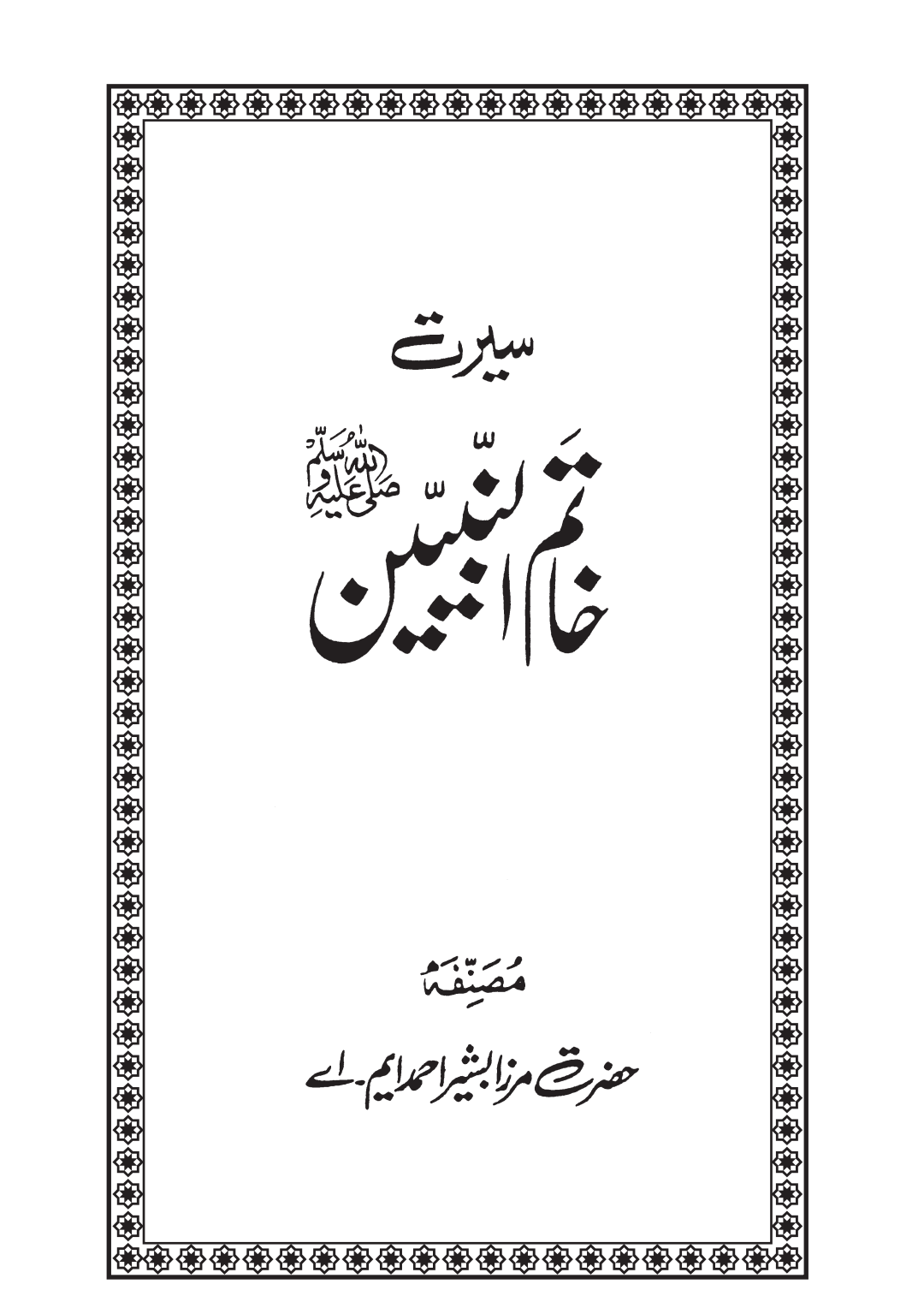Complete Text of Seerat Khatamun-Nabiyeen
Content sourced fromAlislam.org
Page 1
健康康健康康康
مُصَنِّفه
حضرت مرزا بشیر احمد ایم اے
سيرت
Page 2
بیادگار مقدس
حضرت اقدس حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی
سیح موعود و مہدی معہور جرى الله في حلل الانبياء
عليه و على مطاعه محمد الصلوة والسلام
جن کی بعثت کے ذریعہ اس زمانہ میں اللہ کے حکم کے
ساتھ دوبارہ جمال محمدی کا ظہور ہوا.از طرف احقر الخدام
خاکسار
مرزا بشیر احمد
قادیان مورخه ۱۴ شوال ۱۳۳۸ھ
مطابق یکم جولائی ۱۹۲۰ء
Page 3
پیش لفظ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر آج تک ہزاروں کتب لکھی گئی ہیں لیکن حضرت مرزا
بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی تصنیف سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے
کہ اس میں تمام واقعات کی صحت کا مدار سب سے اوّل قرآن کریم اور دوسرے نمبر پر صحاح ستہ پر رکھا گیا
ہے اور کتب تاریخ میں متاخرین کی بجائے ابتدائی مؤرخین اور سیرت نگاروں سے استفادہ کیا گیا ہے.اس لحاظ سے یہ غیر مستند مواد سے پاک ہے اور اس کی صحت اور مستند ہونے پر اعتماد کیا جاسکتا ہے.حضرت میاں صاحب نے اپنی اس تصنیف میں اس امر کا خاص طور پر اہتمام فرمایا ہے کہ مغرب
کے متعصب مستشرقین نے جن مقامات پر تاریخ اسلام کے بعض واقعات کو قابل اعتراض ٹھہرایا ہے یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردارکشی کی کوشش کی ہے آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام
کی روشنی میں ان کا رد فرمایا ہے.آپ نے اپنی اس کتاب میں علاوہ تاریخی مواد کے آج کل زیر بحث
آنے والے بہت سے علمی مسائل مثلاً جمع و ترتیب قرآن کریم معجزہ کی حقیقت ، جہاد بالسیف، غیر مسلموں
سے رواداری، جزیہ ، غلامی ، عورتوں کے حقوق، تعدد ازدواج ، شادی اور طلاق کے متعلق اسلامی قوانین اور
اسلام کی عادلانہ جمہوری طرز حکومت پر سیر حاصل بحث فرمائی ہے.حضرت میاں صاحب نے کمال عشق اور محبت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار کو
موجودہ دور کے ذوق کے مطابق انتہائی دلنشین رنگ میں پیش فرمایا ہے اور فرط عقیدت کے باوجو دسند اور
درایت کے لحاظ سے ضعیف روایات کو اس مجموعہ میں راہ نہیں پانے دی اور واقعات کومستند ماخذ سے ان کے
صحیح تناظر میں پیش فرمایا
ہے.انہی خصوصیات کی بناپر یہ تصنیف بہت مقبول ہوئی.حضرت مصلح موعود خلیفہ مسیح الثانی رضی اللہ عنہ
نے اس کے متعلق فرمایا :
میں سمجھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیر تیں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے
Page 4
یہ بہترین کتاب ہے.اس تصنیف میں ان علوم کا بھی پر تو ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے
ذریعہ حاصل ہوئے.اس کے ذریعہ انشاء اللہ اسلام کی تبلیغ میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی“.سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ایڈیشن ان تین جلدوں پر مشتمل ہے جو ۱۹۲۰ء، ۱۹۳۱ء
اور ۱۹۴۹ء میں شائع ہوئی تھیں ( پہلی جلد پر حضرت میاں صاحب نے بعد میں نظر ثانی بھی فرمائی تھی ).اس طرح یہ مجموعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ے ہجری تک کے حالات پر مشتمل ہے.افسوس ہے کہ حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ با وجود انتہائی خواہش کے اپنی زندگی میں اس مہتم بالشان
علمی شاہکار کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے.حضرت میاں صاحب نے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے
آخری حصہ کے لئے مجوزہ عنوانات بھی اپنے مخصوص انداز میں مرتب فرما کر شائع کر دیے تھے.یہ
عنوانات بھی موجودہ ایڈیشن میں شامل کر دئے گئے ہیں.اس کام کی تکمیل جماعت کے تعلیم یافتہ طبقہ پر
ایک قرض ہے.خدا تعالیٰ کرے کہ ہم اس کو ادا کرسکیں.حضرت میاں صاحب نے اس گرانقدر تصنیف کو محض ایک تاریخ کی حیثیت سے نہیں لکھا بلکہ آپ
کا اوّل ترین مقصد اس سے یہ تھا کہ قوم کے نوجوان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لئے
مشعل راہ قرار دیں.آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
”اے اللہ ! تو اپنے فضل سے ایسا کر کہ تیرے بندے اسے پڑھیں اور اس سے فائدہ اُٹھائیں
اور تیرے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونہ پر چل کر تیری رضا حاصل کریں.جماعت کے ہر فرد کو یہ کتاب پڑھ کر حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ کی اس نیک خواہش کو پورا
کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہئے اور دوسروں کو اسے تحفہ میں دینا چاہئے کیونکہ یہ تصنیف ایک
مثبت دلیل ہے اس عقیدہ وارادت کی جو جماعت احمدیہ کا ہر فر دحضرت خاتم النبیین محمد مصطفی احمد مجتبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتا ہے.آخر میں ان واقف زندگی کا ذکر ضروری ہے جنہوں نے اس ایڈیشن کی تیاری میں مختلف خدمات
سرانجام دی ہیں.سلطان احمد شاہد اور مقصود احمد قمر.احباب انہیں بھی اور خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں
یا درکھیں.
Page 5
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
عرض حال
جلد اوّل
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری جو ہمارا آقا کے نام سے رسالہ ریویو آف ریـلـیـجـنـز
قادیان کے اردو ایڈیشن میں ۱۹۱۹ء کے ابتدا سے شائع ہو رہی ہے اس وقت اس کا پہلا حصہ جو آپ کی مکی
زندگی کے حالات پر مشتمل ہے بعد نظر ثانی کتابی صورت میں ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے.میں نے اپنے
مضمون میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا بلکہ اس زمانہ کی
عام تاریخ اور صحابہ کرام کے حالات پر بھی ہر مناسب موقع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے.گویا مضمون
کے لحاظ سے اس کتاب کا نام در اصل تاریخ اسلام حصہ اوّل سمجھنا چاہئے.میرا ارادہ ہے والله الموفق کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کو تین حصوں
میں تقسیم کروں.پہلا حصہ وہ ہے جو بعض ابتدائی امور ، جغرافیہ عرب، بعثت نبوی کے وقت قبائل عرب کی تقسیم اور
ان کی مذہبی ، تمدنی اور سیاسی حالت، تاریخ کعبه و مکه، تاریخ قریش ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے قبیلہ کے حالات ، آپ کی پیدائش و حالات زندگی تا بعثت ، دعوی نبوت واشاعت اسلام اور
حالات زندگی بعد بعثت تا ہجرت تحریر کئے گئے ہیں.یہ وہ حصہ ہے جو بعد نظر ثانی و مناسب تغیر و تبدل
اب ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے.دوسرا حصہ جو ابھی معرض تحریر میں ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حالات اور اس
زمانے کی اسلامی تاریخ پر مشتمل ہوگا.اور تیسرا حصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ.وهو الموفق
Page 6
اس کتاب کی تصنیف سے میری یہ غرض ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو جو عموماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے حالات زندگی اور ابتدائی اسلامی تاریخ سے بالکل بے خبر ہیں مختصر طور پر عام فہم اور سادہ مگر دلچسپ
پیرا یہ میں صحیح حالات سے واقف کیا جاوے اور نیز یہ بھی کہتا اس ذریعہ سے خدا چاہے تو میرے لئے
سعادت اخروی کا سامان پیدا ہو.یہ ایک نہایت تکلیف دہ منظر ہے کہ ہمارے نوجوان دیگر اقوام و مذاہب کے بادشا ہوں، جرنیلوں اور
مد بروں کے حالات سے تو واقف ہیں اور ان کی سوانح عمریاں پڑھتے ہیں مگر اپنے آقا اور مقتدا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے قطعا نا واقف ہیں.اس کی کئی ایک وجوہات ہیں مگر ایک بڑی وجہ
یہ بھی ہے کہ ابھی تک اُردو زبان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی سوانح عمری نہیں لکھی گئی جو
اس زمانہ کی طبائع کو اپنی طرف کھینچ سکے.مولا ناشبلی کی تصنیف جس کے بعض حصے ابھی تک معرض طبع میں نہیں آئے میرے اس ریمارک سے
مستثنی ہے مگر بعض وجوہات سے وہ بھی عام اسلامی پبلک کے دائرہ تمتمع میں نہیں آ سکتی.بہر حال میری
طبیعت نے اردو لٹر پچر میں ایک کمی کو محسوس کیا ہے جسے پورا کرنے کی میں نے حتی الوسع کوشش کی ہے.اگر
میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں تو زہے قسمت اور اگر نہیں تو خدا سے دعا ہے کہ میری یہ ادھوری اور
ناقص کوشش کسی ایسے نیک دل میں تحریک کرے کہ جو اس کمی کو پورا کر سکے.میں نے اس کتاب کی تیاری کے لئے کسی ایک کتاب پر بھروسہ نہیں کیا خصوصاً متأخرین کی تصنیفات
کو بغیر اپنی مستقل تحقیق کے ہرگز قابل اعتماد نہیں سمجھا.متقدمین میں سے چار کتب تاریخی طور پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح کے لئے اصل مآخذ مجھی گئی ہیں.اعنی اول سیرۃ ابن ہشام جو سیرۃ ابن اسحاق
سے ماخوذ ہے.دوسرے طبقات ابن سعد.تیسرے طبری اور چوتھے واقدی.ان سب کا میں نے
حتی الوسع با قاعدہ مطالعہ کیا ہے اور سب سے فائدہ اُٹھایا ہے.ان کتب کے بیان کردہ واقعات کی چھان
بین اور تحقیق کے واسطے میں نے قرآن شریف اور کتب احادیث خصوصاً صحاح ستہ کو حتی الوسع ہمیشہ اپنے
سامنے رکھا ہے.متآخرین کی کتب میں سے زرقانی، شرح مواہب اللہ نیہ، تاریخ الکامل ابن اثیر، اسد
الغابہ اور اصابہ فی معرفۃ الصحابہ اور سیرۃ النبی مصنفہ مولانا شبلی سے میں نے بہت فائدہ اُٹھایا ہے.یورپ
کے اعتراضات اور طرز تحریر کو مد نظر رکھنے کے واسطے میں نے لائف آف محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) مصنفہ سر
ولیم میور، محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) مصنفہ پروفیسر مارگولیس اور بعض دیگر تصنیفات کو زیر مطالعہ رکھا ہے.
Page 7
جغرافیہ عرب کے واسطے معجم البلدان کو میں نے نہایت کار آمد اور قابلِ اعتبار رفیق پایا ہے.جامعیت کے
لحاظ سے تاریخ خمیس اور سیرۃ الحلبیہ کا میں نے جواب نہیں دیکھا مگر افسوس تحقیق سے خالی ہیں.غرض میں نے اپنی طرف سے پوری تحقیق اور چھان بین سے کام لیا ہے مگر الانسان مــركـب من
الخطاء و النسيان فارجو ممن طالع کتابی هذا ان يسامحنى اذا وقف على خطاء اوسهو
فيه و يدعوا الله ان يهدينى الى الصراط المستقيم فانه لا مضل لمن هداه و لا هادى لمن
ا ا
اضله بيده الخير كله و هو المستعان
اس کتاب کی تیاری میں جن احباب کی طرف سے مجھے کسی قسم کی مددپہنچی ہے ان سب کا میں دلی شکریہ
ادا کرتا ہوں.خصوصاً استاذی المکرم حضرت مولوی شیر علی صاحب بی اے ایڈیٹر ریویو آف ریلیجنز
قادیان کا جن کے مفید مشورہ سے میں نے بہت فائدہ اُٹھایا ہے اور مکر می جناب مولوی فضل دین صاحب
وکیل قادیان کا جنہوں نے مسودوں کے مطالعہ کے علاوہ مجھے ضروری حوالجات کی تلاش میں بہت مدددی
اور مکرمی ماسٹر احمد حسین صاحب فرید آبادی ثم قادیانی کا جنہوں نے ادبی لحاظ سے مضمون میں مناسب
اصلاح کی.خاکسار
مرزا بشیر احمد
۱۴ رشوال ۱۳۳۸ھ مطابق یکم جولائی ۱۹۲۰ء
Page 8
۴
۶
1.۴۷
۵۷
۵۹
۶۸
۷۳
۷۳
۷۶
LL
۸۵
AL
i
فہرست مضامین
سيرة خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
تاریخ اسلام کے ابتدائی ماخذ
قبل از اسلام روایات واشعار
قرآن شریف
تاریخ اسلام کے روایتی ماخذ
عرب کا ملک اور اس کے باشندے
ظہوراسلام سے پہلے عرب کا تہذیب و تمدن
تعلیم اور قدیم شاعری
عورت کی حیثیت
قدیم مذاہب عرب
مکہ کعبہ اور قریش
ابوالانبیاء خلیل اللہ
اسماعیل ذبیح اللہ -
حصّہ اوّل
حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے متعلق بعض اعتراضات کا جواب
تعمیر کعبہ
تولیت کعبه
Page 9
۸۹
۹۲
۹۳
1+1
۱۰۵
۱۰۵
11 +
۱۱۳
۱۱۷
۱۱۸
119
۱۲۱
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۸
۱۳۳
ܬܪܙ
ܬܪܙ
۱۸۶
۱۸۹
٢٠٣
۲۰۳
۲۰۳
۲۰۶
!!
کعبہ کی دوبارہ ، سہ بارہ تعمیر
نقشه کعبه و مسجد حرام
قریش
چاہ زمزم کی تلاش
اصحاب الفیل
ابتدائی زندگی
ولادت با سعادت
کفالت
سفر شام
حرب فجار
حلف الفضول
مشاغل تجارت
حضرت خدیجہ سے شادی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد
کعبہ کی جدید تعمیر
ابتدائی زندگی پر ایک سرسری نظر
آغاز رسالت
ایام
کش مکش
ہجرت حبشہ
مسلمانوں کے خلاف معاہدہ قریش اور مسلمانوں کا بائیکاٹ
شق القمر کا معجزہ
توسیع اشاعت
قبائل کا دورہ
طائف کا سفر
آپ کی خدمت میں جنات کا وفد
Page 10
۲۱۰
۲۱۲
۲۳۲
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۵۲
۲۶۲
۲۶۵
۲۷۰
۲۹۱
۲۹۴
۲۹۷
۳۰۱
٣٠٣
۳۰۹
۳۱۱
۳۱۸
۳۲۲
۳۳۰
!!!
قبیلہ دوس میں اسلام
معراج اور اسراء
پنجگانہ نماز کا فرض ہونا
سلطنت ہائے روم فارس کی جنگ اور اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی
قبائل عرب کو تبلیغ اسلام
وطن سے بے وطن
یثرب میں اسلام
بیعت عقبہ اولی
بیعت عقبہ ثانیہ
آغاز سفر ہجرت اور قریش کا تعاقب
سفر ہجرت اور سراقہ بن مالک کا تعاقب
مکی زندگی پر ایک سرسری نظر
حصّہ دوم
مدینہ کا ابتدائی قیام اور حکومت اسلامی کی تاسیس -
نزول قباء
ورود مد ینہ اور جمعہ کی پہلی نماز
تعمیر مسجد نبوی
ابتدائے اذان
مواخات انصار و مهاجرین
مدینہ کی سوسائٹی کی تقسیم اور یہود کے ساتھ معاہدہ
قبائل عرب کی متحدہ مخالفت
جہاد بالسیف کا آغاز اور اصولی بحث
کبھی کوئی شخص جبراً مسلمان
نہیں بنایا گیا
صحابہ کی زندگیاں جبر کے خیال کی مکذب ہیں
Page 11
} } }
۳۵۶
NNNE
۳۸۲
۳۸۴
۳۹۵
۴۲۷
۴۲۹
۴۴۹
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۳
۴۷۲
iv
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی خواہش جبر کے خیال کو جھٹلاتی ہے
فتح مکہ کے موقع پر سینکڑوں کفارا سلام سے منکر رہے
وجوہات جنگ
اسلامی آداب جہاد
ابتدائی لڑائیاں.روزہ کی ابتداء.تحویل قبلہ
اور جنگ بدر کے متعلق ابتدائی بحث
غزوات و سرایا کا آغاز
تحویل قبلہ
صیام رمضان
عید الفطر
جنگ بدر کے متعلق ایک ابتدائی بحث
جنگ بدر.اسلامی سلطنت کا استحکام اور رؤساء قریش کی تباہی
رومی سلطنت کی فتح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی
غلاموں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
سلوک اور مسئلہ غلامی کے متعلق آپ کی تعلیم.مسلمانوں نے غلامی کی آزادی کی تعلیم پر کس طرح عمل کیا
آزادشدہ غلاموں کے لئے تمام ترقی کے دروازے کھلے تھے
تمام غلاموں کو یکلخت کیوں نہ آزاد کر دیا گیا
اسلامی ممالک میں غلامی کیوں قائم رہی
غلاموں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت.آئندہ غلامی کو روکنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم -
جنگی قیدیوں کا مسئلہ
لونڈیوں کا مخصوص مسئلہ
حضرت عائشہ کا رخصتانہ اور ان کی عمر کی بحث
تعددازدواج کا مسئلہ.دو فرضی واقعات
Page 12
۵۱۱
۵۱۳
۵۲۲
۵۲۴
۵۲۷
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۳
۵۸۷
۵۹۴
۵۹۶
۵۹۷
۶۰۶
۶۱۵
۶۲۵
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۶
۶۴۶
۶۵۲
قبائل نجد اور یہود کے ساتھ جنگ کا آغاز.حضرت فاطمہ
اور حفصہ کی شادی اور بعض متفرق واقعات
عید الاضحی
جنت البقیع اور اس کا پہلا مدفون
تزویج ام کلثوم
قتل کعب بن اشرف
ولادت امام حسن
ایک مصیبت کا دھکہ.قانون ورثہ.حرمت شراب
کفار کی غداری اور دو دردناک واقعات
جنگ احد
غزوہ حمراء الاسد
یہود کی دوسری غداری.جمع و ترتیب قرآن.حضرت زینب
کی شادی.واقعہ افک اور منافقین کی فتنہ پردازی.ولادت حسین
تزوج ام سلمه
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب خاص اور عبرانی کی تعلیم -
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بین الاقوامی قاضی کی حیثیت میں
مدینہ میں خسوف قمر اور صلوٰۃ خسوف
پردے کے احکام کا نزول
کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مفید مطلب وحی اتارلیا کرتے تھے
جو میر یہ بنت حارث کی شادی
عزل یعنی برتھ کنٹرول کی اجازت
مدینہ کا محاصرہ اور مسلمانوں کی نازک حالت - کفار کی نامرادی.حقیقت معجز
جنگ احزاب
معجزہ کی حقیقت
Page 13
۶۷۴
۶۸۲
۶۹۲
۶۹۶
۷۱۳
ZIA
۷۲۰
۷۲۳
۷۲۷
۷۳۱
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۷
۷۴۹
۷۵۳
۷۵۷
۷۵۸
vi
بنو قریظہ کی غداری اور مدینہ میں یہود کا خاتمہ.قانون شادی و طلاق.ریحانہ کا غلط واقعہ
انصار کے رئیس اعظم کی وفات اور نعماء جنت کی حقیقت
فنون سپاہ گری کی طرف توجہ
مدنی زندگی کے پہلے دور کا خاتمہ اور اسلامی طریق حکومت
حکومت کا حق صرف جمہور کو حاصل ہے
حکومت کے لئے مشورہ ضروری ہے
بنوامیہ کی خلافت صحیح اسلامی خلافت نہ تھی
کیا امارت سے دستبرداری کی جاسکتی ہے
اسلامی اطاعت کا معیار
کیا امارت کا حق صرف قریش کے ساتھ مخصوص ہے
غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات
مذہبی رواداری
جزیہ کا مسئلہ
عام سلوک اور سیاسی تعلقات
عدل وانصاف
غریب ذمیوں کی امداد
دوسری اقوام کے مذہبی بزرگوں کا احترام
حصہ سوم
مدنی زندگی کے دوسرے دور کا آغاز اور صلح حدیبیہ سے پہلے کا زمانہ -
ثمامہ بن اثال رئیس بیمامہ کا اسلام لانا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ستر ہزار آدمی بلا حساب جنت میں جائیں گے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادا بوالعاص کا مسلمان ہونا
ایک مسلمان اور کافر کے ازدواجی تعلق کے متعلق اسلامی تعلیم
Page 14
۷۶۳
۷۶۴
LLL
۷۸۰
ZAM
۷۸۳
۷۸۴
ZAZ
۷۹۱
۷۹۳
۷۹۵
۷۹۷
ووے
۸۰۸
۸۱۲
MZ
۸۱۹
۸۳۰
۸۳۳
۸۳۶
۸۴۱
ΑΛΙ
vii
سفر سے واپسی کی دعا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ریہ کا الزام -
زید بن حارثہ کی امارت پر لوگوں کا اعتراض اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب
مساوات اسلامی پر ایک مختصر نوٹ
عام تعلقات میں مراتب کو ملحوظ رکھنے کی تلقین
سوشل اجتماعوں میں برادرانہ اختلاط
خادم و آقا کے تعلقات
بیاہ شادی کے معاملات میں اسلامی تعلیم
مرد و عورت میں حقوق کی مساوات
اسلام میں دولت کی تقسیم کا نظریہ
معذور لوگوں کی ذمہ داری حکومت پر ہے
اقتصادی مساوات کے متعلق ایک خاص نکتہ
اسلام ایک وسطی نظریہ پیش کرتا ہے
استثنائی حالات میں خوراک کی مساویانہ تقسیم.دینی اور روحانی امور میں مساوات
ام قرفہ کے قتل کا غلط واقعہ
اہل خیبر کی شرارت اور ابورافع یہودی کا قتل
مدینہ میں بارش کا قحط اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استسقاء
اسلام میں قبولیت دعا کا مسئلہ
اہل خیبر کی طرف سے مزید خطرہ اور قتل اسیر بن رزام
نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش
قبائل شکل و عربیتہ کی غداری
صلح حدیبیہ اور اس کے عظیم الشان نتائج
بیعت رضوان
اسلامی سیاست اسلام کے دینی نظام سے علیحدہ بھی ہوسکتی ہے
Page 15
۸۸۴
۸۸۹
۸۸۹
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۶
۸۹۷
۹۰۰
۹۱۱
۹۱۶
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۷
۹۴۹
viii
اسلام کی امن اور جنگ کی طاقت کا مقابلہ
اسود و احمر کے نام اسلام کا پیغام
قیصر و کسری کو دعوت حق
اسلام کا تبلیغی نظریہ
دین کے معاملہ میں جبر جائز نہیں
اسلام کا عالمگیر مشن
اسلام کی دائمی شریعت
انگوٹھی کی تیاری
عرب کے چاروں اطراف میں تبلیغی مہم
قیصر و کسریٰ کی باہمی کشمکش اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیشگوئی
ہر قل کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط
کسری کے نام خط
مقوقس مصر کے نام خط
مقوقس والے خط کا عکس
نجاشی کے نام تبلیغی خط
رئیس غسان کے نام خط
رئیس یمامہ کے نام خط
جوئے اور شطرنج کی ممانعت
مجوزہ عناوین
سيرة خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض آراء
Page 16
فارسی
شمال
مشرق.مغرب
اين
۱۰۰ کیلا وشر
السود..الاحقاف
"20
مارب
تيماء
مدائن صالح.المدينة المنورة
اسكت
مكة المكرمة
الطائف
القدس
تبوك
اکسوم
صنعاء
الحبشة
Page 17
صلی اللہ علیہ وسلم
سیرت خاتم النبین
حصّہ اوّل
Page 18
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
سیرت نبوی اور تاریخ اسلام
کے ابتدائی ماخذ
اسلام کا آغاز ایک ایسے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جو اکثر ملکوں کے لئے ایک غیر تا ریخی زمانہ تھا
جب کہ نہ صرف ابھی مطبع کی ایجاد عالم وجود میں نہیں آئی تھی بلکہ فن تحریر وتصنیف بھی ابھی بالکل ابتدائی
مراحل میں تھا.معروف مسیحی سنہ کی رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ۵۷ ء سے لے کر ۶۳۲ ء تک
قرار دیا گیا ہے.یہ وہ زمانہ ہے جب کہ اکثر اقوام عالم فن تصنیف سے بالکل نا آشنا تھیں اور صرف ایسی
قوموں میں کسی حد تک اس کا رواج پایا جاتا تھا جو کسی نہ کسی جہت سے علمی یا سیاسی رنگ میں ترقی یافتہ تھیں،
لیکن جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوگا ، اسلام سے پہلے عرب کا ملک نہ صرف بیرونی دنیا سے بالکل منقطع تھا
بلکہ اندرونی تحریکات کے لحاظ سے بھی ہر قسم کی علمی اور سیاسی اور تمدنی تحریک سے کلیۂ خالی تھا، اس لیے گو
اسلام سے پہلے بھی عرب میں بعض لکھے پڑھے لوگ پائے جاتے تھے مگر ان کا مبلغ علم محض نوشت و خواند
تک محدود تھا اور اسلام سے پہلے زمانہ کی کوئی عربی تصنیف یا اس زمانہ کے متعلق عرب کی تاریخ کا کوئی
ریکارڈ محفوظ نہیں ہے.بے شک بعض قدیم اقوام عرب کے آثار و کتبات موجود ہیں، لیکن عرب جیسے ملک
کی تاریخ کے لیے یہ ماخذ کسی صورت میں مربوط اور تفصیلی معلومات کی بنیاد نہیں بن سکتا.دوسرے درجہ پر ان قوموں اور حکومتوں کا ریکارڈ ہے جو اس زمانہ میں عرب کے پہلو میں واقع تھیں.جن میں سلطنت ہائے روم و فارس خاص طور پر قابل ذکر ہیں.ان کے ساتھ چونکہ عرب کی حدود ملتی تھیں
Page 19
اس لیے ان حکومتوں کی تاریخ میں کہیں کہیں عرب کا ذکر بھی آجاتا ہے، مگر لازماً یہ ذکر بہت مختصر ہے اور
صرف جزوی امور سے تعلق رکھتا ہے اور ملک کے اندرونی حالات کے متعلق اس ضمنی تذکرہ سے کوئی
بصیرت پیدا نہیں ہوسکتی.اسی ذیل میں یہودی اقوام کی تاریخ اور بائیبل کا نام بھی لیا جاسکتا ہے جن میں
کہیں کہیں عرب کے متعلق اشارات پائے جاتے ہیں.قبل از اسلام روایات واشعار تیسرے درجہ پر خود عرب کی اندرونی روایات ہیں اور دراصل
عرب کی تاریخ قبل از اسلام کے لیے یہی روایات بطور بنیاد
کے ہیں.عرب میں فنِ تحریر و تصنیف کا رواج نہیں تھا لیکن زبانی روایات کو سینہ بہ سینہ محفوظ رکھنے کی طرف
عام توجہ تھی اور اس غرض کے لیے عربوں کا حافظہ اس غضب کا تھا کہ اس کی مثال کسی دوسری قوم میں نظر نہیں
آتی.ہر قبیلہ میں ایک خاص طبقہ ایسے لوگوں کا ہوتا تھا جو اپنے قبیلہ بلکہ آس پاس کے ہمسایہ قبیلوں کی
تاریخ کو بھی پوری صحت اور وفاداری کے ساتھ یاد رکھتے تھے.اس فن کو عربوں میں علم انساب یعنی نسب
ناموں کا علم کہتے تھے.تاریخ میں زمانہ قبل از اسلام کے کئی لوگوں کا نام اس فن کے ماہرین کے طور پر
بیان ہوا ہے.اسی طرح یہ علم ایک نسل سے دوسری نسل تک اور دوسری سے تیسری تک چلتا چلا جا تا تھا اور
ہر قبیلہ کی تاریخ اس کے راویوں کے سینوں میں محفوظ رہتی تھی.اس ضمن میں ایک خاص ذریعہ قدیم تاریخ عرب کی حفاظت کا وہ اشعار بھی ہیں جو قبل از اسلام
شاعروں نے کہے ہیں کیونکہ ان میں بھی خاص خاص حصے قبائل عرب کی تاریخ کے آ جاتے ہیں.اسلام
سے پہلے زمانہ میں عربوں میں شعر کا فن اس کمال کو پہنچا ہوا تھا کہ بعض ناقدین شعر کی رائے میں باوجود
اسلامی شعراء کی ترقی کے اسلامی زمانہ بھی بعض بہت سے اس کی مثال پیش نہیں کرتا.عربوں کی زندگی
قبائلی تمدن کا رنگ رکھتی تھی.اور قریباً ہر قبیلہ میں کوئی نہ کوئی شاعر ہوتا تھا جو اپنے قبیلہ کے خاص خاص
حالات کو اپنے زور دار بدویا نہ اشعار میں محفوظ رکھتا تھا.اور عربوں کی عادت تھی کہ ان اشعار کو یاد رکھتے
اور اپنی مجالس میں سناتے رہتے تھے.زمانہ جاہلیت کے شعراء میں امراء القیس ، نابغہ ذبیاتی، زہیر، طرفہ،
عنتره، علقمه، اعشی، عمرو بن كلثوم، امیہ بن ابی صلت، کعب بن زہیر ، لبید ، حسان بن ثابت ، خنساء وغیرہ
لے : ”لائف آف محمد" مصنفه سرولیم میور ایڈیشن ۱۸۹۴ صفحه ۶ دیباچه
: ”لائف آف محمد “ میور دیباچه صفحه ۴۶
سے : اسلامی اصطلاح میں عرب
کا زمانہ قبل از اسلام جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے.
Page 20
خاص شہرت رکھتے ہیں.جن کے بہت سے اشعار آج تک محفوظ ہیں اور اس قدر حیرت انگیز فصاحت اور
زور بیان اور قلمی مصوری کا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ وہ اُس زمانہ کی کسی قوم اور کسی ملک کی شاعری میں نظر
نہیں آتا.مذکورہ بالا شعراء میں سے مؤخر الذکر چار شاعر جن میں آخر الذکر ایک مشہور شاعرہ کا نام ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے لیے
ہمارا یہ بیان کہ عربوں کی تاریخ قبل از اسلام زبانی روایتوں میں محفوظ تھی بعض نا واقف لوگوں کو تعجب
میں ڈالے گا کہ ایک وسیع ملک کی تاریخ جو سینکڑوں سالوں پر پھیلی ہوئی ہو محض زبانی روایتوں میں کس طرح
محفوظ رہ سکتی ہے؟ لیکن ہمارے ناظرین کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ اقوامِ عالم
کی تاریخ اسی قسم کی زبانی روایات تک محدود ہوتی تھی.صرف فرق یہ ہے کہ جہاں بہت سی قوموں میں یہ
روائتیں ایک غیر محفوظ صورت میں زبان زد خاص و عام تھیں اور بعد میں تاریخی زمانہ میں آ کر وہ جس
صورت میں پائی گئیں ، جمع کر لی گئیں.وہاں اس غیر تاریخی زمانہ میں بھی عربوں میں ان روایتوں کی
حفاظت کا بہت سی دوسری قوموں کی نسبت بہتر انتظام تھا.کیونکہ ان میں یہ دستور تھا کہ اپنے قبیلہ کی تاریخ
کو روایات یا اشعار کے ذریعہ یا درکھتے تھے اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ عربوں کا حافظہ اس غرض کے لیے خاص
طور پر ترقی یافتہ تھا.بہر حال عرب کی قبل از اسلام تاریخ کے لئے عربوں کی زبانی روایات جو بعد میں
تحریری طور پر بھی ضبط میں آ گئیں ، سب سے بڑا ماخذ ہیں.اور چونکہ ان کی مدد کے بغیر قدیم تاریخ عرب
کا ڈھانچہ تیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کوئی مورخ انہیں نظر انداز نہیں کرسکتا.ان روایات
کا تحریری ضبط بعد
کی کئی کتابوں میں موجود ہے، مگر سب سے زیادہ مکمل صورت میں مشہور اسلامی مؤرخ ابو جعفر محمد ابن جریر
طبری کی تاریخ میں پایا جاتا ہے جس میں اس منتشر مواد کے بیشتر حصہ کو ایک مربوط صورت میں ایک جگہ
جمع کر دیا گیا ہے اور بعد کی اکثر کتا ہیں کم و بیش اسی مجموعہ کی خوشہ چین ہیں.اسلام کی آمد سے عرب کی تاریخ میں ایک بالکل نئے باب کا آغاز ہوا.محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز
نے عرب کی سوئی ہوئی طاقتوں کو اس طرح بیدار کر دیا تھا، جیسے ایک گہری نیند سو یا ہوا شخص کسی اچانک شور
سے چونک کر بیدار ہو جائے.اور اس وقت سے عرب کی تاریخ میں بھی ایک انقلابی صورت پیدا ہوگئی.جیسے کہ ایک تاریکی میں چھپی ہوئی چیز یک لخت سورج کی تیز روشنی کے سامنے آ جائے.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح اور آغاز اسلام کی تاریخ کے متعلق اس قدر مضبوط تاریخی مواد موجود ہے
ل : كتاب الشعرو الشعراء لابن قتيبه
۲ : ۲۲۴ ھ تا ۳۱۰ھ
Page 21
کہ یقیناً اس سے بڑھ کر آج تک کسی مذہب اور کسی بانی مذہب کو نصیب نہیں ہوا.یہ مواد متعد دصورتوں
میں پایا جاتا ہے اور ہم ان مختلف صورتوں کا ایک اجمالی نقشہ ذیل کے اوراق میں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں.قرآن شریف سب سے اول نمبر پر اسلامی تاریخ کا وہ مضبوط قلعہ ہے جو قرآن شریف کے نام سے
یاد کیا جاتا ہے.مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق قرآن شریف کا ایک ایک لفظ اور
ایک ایک حرف خُدا کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بصورت وحی نازل ہوا.یہ نزول
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ نبوت کی زندگی پر پھیلا ہوا تھا.یعنی الہام سے ہی آپ کے دعوئی
کی ابتداء ہوئی اور قرآن شریف کا آخری حصہ اس وقت نازل ہوا جب کہ آپ کی وفات بالکل قریب
تھی.اس طرح اگر آپ کی نبوت کے مجموعی ایام کے مقابلہ پر قرآنی آیات کی مجموعی تعداد کو رکھ کر دیکھا
جائے تو روزانہ نزول کی اوسط ایک آیت سے بھی کم بنتی ہے کیونکہ جہاں آپ کی نبوت کے ایام کم و بیش
سات ہزار نوسوستر بنتے ہیں وہاں قرآنی آیات کی تعداد صرف چھ ہزار دو سو چھتیں ہے اور چونکہ قرآنی الفاظ
کی مجموعی تعدا د ستر ہزار نو سو چونتیس ہے اس لیے فی آیت بارہ الفاظ کی اوسط ہوئی جس سے روزانہ نزول
کی اوسط کم و بیش نو لفظ سمجھی جاسکتی ہے.ان اعداد و شمار سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف بہت ہی آہستہ آہستہ
نازل ہوا تھا.اور گو یہ درست ہے کہ قرآن شریف کے نزول میں بعض اوقات ناغے بھی آ جاتے تھے
اور بعض دوسرے ایام میں ایک ہی وقت میں متعدد آیات اکٹھی نازل ہو جاتی تھیں.لیکن پھر بھی
قرآن شریف کبھی بھی ایک وقت میں اتنی مقدار میں نازل نہیں ہوا کہ اُسے لکھ کر محفوظ کرنے یا ساتھ ساتھ
یاد کرتے جانے میں کوئی مشکل محسوس ہوئی ہو.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جو جو آیات قرآن شریف کی نازل ہوتی جاتی تھیں انہیں
ساتھ ساتھ لکھواتے جاتے اور خدائی تفہیم کے مطابق ان کی ترتیب بھی خود مقرر فرماتے جاتے تھے.اس
بارے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل حدیث بطور مثال کے پیش کی جاسکتی ہے.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَانَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ
ضَعُوا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِى سُورَةِ الَّتِى يَذْكُرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا فَإِذَانَزَلَتْ عَلَيْهِ
ل : كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطی جز واوّل صفحہ ۶۷،۶۶
Page 22
الْآيَةُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِى السُّورَةِ الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا
د یعنی حضرت ابن عباس جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے روایت
کرتے ہیں کہ حضرت عثمان خلیفہ ثالث ( جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کاتب
وحی رہ چکے تھے ) فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیات اکٹھی نازل
ہوتی تھیں تو آپ اپنے کاتبان وحی میں سے کسی کو بلا کر ارشاد فرماتے تھے کہ ان آیات کو فلاں
سورۃ میں فلاں جگہ لکھو اور اگر ایک ہی آیت اُترتی تھی تو پھر بھی اسی طرح کسی کاتب وحی کو بلا کر
اور جگہ بتا کر اسے تحریر کروادیتے تھے.“
جن صحابہ سے کاتب وحی کا کام لیا جاتا تھا اُن کے نام اور حالات تفصیل و تعیین کے ساتھ تاریخ میں
محفوظ ہیں.ان میں سے زیادہ معروف صحابہ یہ تھے.حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان ، حضرت علیؓ،
زبیر بن العوام ، شرجیل بن حسنہ، عبد اللہ بن رواحہ، ابی بن کعب اور زید بن ثابت.اس فہرست سے ظاہر
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے اسلام سے ہی ایک معتبر جماعت قرآنی وحی کے قلمبند کرنے
کے لیے میسر رہی تھی اور اس طرح قرآن شریف نہ صرف ساتھ ساتھ تحریر میں آتا گیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ
اس کی موجودہ ترتیب بھی جو بعض مصالح کے ماتحت نزول کی ترتیب سے جدا رکھی گئی ہے قائم ہوتی گئی
تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کہ نزولِ قرآن مکمل ہو چکا تھا حضرت ابوبکر خلیفہء
اول نے حضرت عمرؓ کے مشورہ سے زید بن ثابت انصاری کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی رہ
چکے تھے حکم فرمایا کہ وہ قرآن شریف کو ایک باقاعدہ مصحف کی صورت میں اکٹھا لکھوا کر محفوظ کر دیں.چنانچہ زید بن ثابت نے بڑی محنت کے ساتھ ہر آیت کے متعلق زبانی اور تحریری ہر دو قسم کی پختہ شہادت مہیا
کر کے اسے ایک باقاعدہ مصحف کی صورت میں اکٹھا کر دیا.اس کے بعد جب اسلام مختلف ممالک میں
پھیل گیا تو پھر حضرت عثمان خلیفہ ثالث کے حکم سے زید بن ثابت کے جمع کردہ نسخہ کے مطابق قرآن شریف
کی متعدد مستند کا پیاں لکھوا کر تمام اسلامی ممالک میں بھجوا دی گئیں ہے
ل : ترندی وابوداؤد مسند احمد بحوالہ مشکوۃ ابواب فضائل القرآن
: فتح الباری جلد و صفحه ۱۹ وزرقانی جلد ۴ صفحه ۳۱ تا ۳۲۶
: بخاری کتاب فضائل القرآن باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
: بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن و فتح الباری جلد 9 صفحہ ۱۸،۱۷
Page 23
دوسری طرف قرآن شریف کے حفظ کرانے کا ایسا انتظام تھا کہ اس کے نزول کے ساتھ ساتھ صحابہ کی
ایک جماعت اُسے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق حفظ کرتی جاتی تھی اور گونجز وی طور پر حفظ کرنے والوں کی
تعداد تو بہت زیادہ تھی مگر آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سارے قرآن کے حافظ بھی کافی تعداد
میں موجود تھے جن میں سے کم از کم چار ایسے تھے جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجربہ کر کے اور ہر
طرح قابلِ اعتماد پا کر دُوسرے صحابہ کی تعلیم کے لیے مقرر فرمایا تھا.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے بعد تو جب کہ قرآن شریف مکمل ہو کر ایک مصحف کی صورت میں آچکا تھا، حفاظ قرآن کی تعداد
نے ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ ترقی کی کہ حضرت عمرؓ کے عہد میں صرف ایک جگہ کی اسلامی فوج میں
تین سو سے زائد حافظ قرآن موجود تھے.ان اسباب کے نتیجہ میں جن کے پیچھے خدائی حفاظت کا ہاتھ کام
کر رہا تھا، ابتدائے اسلام سے ہی قرآن شریف کا متن ہر قسم کی تحریف اور دست بُرد کے خطرہ سے محفوظ ہو
گیا تھا.اور اس زمانہ کے بعد تو اس کے مستند نسخے اس طرح مختلف ممالک میں پھیل گئے اور حفاظ قرآن کی
تعداد اتنی زیادہ ہوگئی کہ تحریف کا امکان ہی باقی نہیں رہا.اور جیسا کہ دوست و دشمن سب نے تسلیم کیا
ہے
اس بات میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ آج کا قرآن بغیر کسی زیر وزبر کے فرق کے وہی
ہے جو آج سے تیرہ سو سال قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا.اس بارہ میں مثال کے طور پر
بعض عیسائی محققین کی رائے درج ذیل کی جاتی ہے:
سرولیم میور لکھتے ہیں :
”دنیا کے پردے پر غالباً قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو بارہ سو سال کے طویل
عرصہ تک بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے اپنی اصلی صورت میں محفوظ رہی ہو.“
پھر لکھتے ہیں :
”ہماری اناجیل کا مسلمانوں کے قرآن کے ساتھ مقابلہ کرنا جو بالکل غیر محرف ومبدل
چلا آیا ہے دو ایسی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے جنہیں آپس میں کوئی بھی نسبت نہیں.“
پھر لکھتے ہیں :
اس بات کی پوری پوری اندرونی اور بیرونی ضمانت موجود ہے کہ قرآن اب بھی اُسی
شکل وصورت میں ہے جس میں کہ محمد نے اُسے دُنیا کے سامنے پیش کیا تھا.“
: بخاری فضائل القرآن
: کنز العمال باب فی القرآن فصل فی فضائل القرآن
Page 24
پھر لکھتے ہیں :
”ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت محمد سے لے کر آج تک اپنی
اصلی اور غیر محرف صورت میں چلی آئی ہے.166
نولڈ کی جو جرمنی کا ایک نہایت مشہور عیسائی مستشرق گذرا ہے اور جو اس فن میں گویا اُستاد مانا گیا ہے
قرآن شریف کے متعلق لکھتا ہے کہ : -
یورپین علماء کی یہ کوشش کہ قرآن میں کوئی تحریف ثابت کریں قطعا نا کام رہی ہے.“
اس خصوصیت کے علاوہ کہ قرآن شریف اپنے زمانہ نزول سے لے کر آج تک بالکل محفوظ چلا آیا
ہے، ایک بڑی خصوصیت قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ بوجہ اس کے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
تئیس سالہ نبوت کی زندگی کے دوران میں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا تھا.آپ کی نبوت کی زندگی کا کوئی
حصہ ایسا نہیں ہے جس پر قرآن شریف کے کسی نہ کسی حصہ سے براہ راست روشنی نہ پڑتی ہو اور یہی حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کی عملی تفسیر ہے کہ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ساری سیرت قرآن میں آجاتی ہے.گویا قرآن شریف وہ کتاب ہے جس میں آپ کے اخلاق و
عادات اور آپ کی روزانہ زندگی کے حالات ہر روز ساتھ ساتھ قلمبند ہوتے جاتے تھے اور یقیناً دنیا کی
تاریخ میں اور کوئی ایسا شخص نہیں گذرا جس کی سیرت کے متعلق اس قدر مضبوط اور مستند عصری ریکارڈ محفوظ
ہو.بیشک بعض ایسے لوگ گزرے ہیں اور اس زمانہ میں بھی پائے جاتے ہیں جن کی سوانح عمریاں ان کی
زندگی میں ہی یا ان کی وفات کے جلد بعد شائع ہو گئی ہیں مگر جو خصوصیت قرآن شریف کے وجود میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ گویا آپ کی روزانہ زندگی ہر روز ساتھ ساتھ ضبط میں آتی گئی
ہے وہ آج تک کسی اور فرد بشر کو نصیب نہیں ہوئی.مغربی محققین نے قرآن شریف کی اس خصوصیت کا بھی
کھلے الفاظ میں اقرار کیا ہے؛ چنانچہ سرولیم میورلکھتا ہے:
قرآن کی یہ خصوصیت اس قدر اہم ہے کہ اس میں کسی مبالغہ کی گنجائش نہیں.اس
خصوصیت کی وجہ سے محمد کی سیرت و سوانح اور آغاز اسلام کی تاریخ کے لئے قرآن ایک بنیادی
: لائف آف محمد دیبا چه صفحه ۲۱ ۲۲، ۲۶،۲۵
: انسائیکلو پیڈیا برٹینی کا زیر لفظ قرآن
: صحیح مسلم، ابوداؤد و نسائی بحوالہ تفسیر ابن کثیر زیر تیسیر اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم:۵)
Page 25
چیز قرار پاتا ہے جس سے ان ہر دو کے متعلق تمام تحقیق طلب امور کو پوری صحت کے ساتھ جانچا
جاسکتا ہے.قرآن شریف میں ہمیں وہ ذخیرہ میسر ہے جس میں محمد کے الفاظ خود آپ کی زندگی
میں محفوظ کر لیے گئے تھے.اور یہ ریکارڈ آپ کی زندگی کے ہر حصہ سے یعنی آپ کے مذہبی
خیالات سے، آپ کے پبلک افعال سے، آپ کی خانگی سیرت سے یکساں تعلق رکھتا ہے...حقیقۂ محمد کی سیرت کے لئے قرآن ایک ایسا سچا آئینہ ہے کہ اسلام کے سارے ابتدائی زمانہ
میں یہ بات بطور ایک مثل اور کہاوت کے مشہور تھی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی ساری سیرت
قرآن میں ہے.پھر انگلستان کا مشہور مسیحی مستشرق پروفیسر نکلسن اپنی انگریزی تصنیف ”عرب کی ادبی تاریخ “ میں
لکھتا ہے:
اسلام کی ابتدائی تاریخ کا علم حاصل کرنے کے لیے قرآن ایک بے نظیر اور ہر شک وشبہ
سے بالا کتاب ہے اور یقیناً بدھ مذہب یا مسیحیت یا کسی قدیم مذہب کو اس قسم کا مستند عصری
،،
ریکارڈ حاصل نہیں ہے ، جیسا کہ قرآن میں اسلام کو حاصل ہے.الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح کے لیے قرآن شریف نہ صرف اسلامی لٹریچر میں
سب سے زیادہ مستند اور صحیح ریکارڈ ہے بلکہ آپ کی سیرت کے تعلق میں اسے وہ پوزیشن حاصل ہے جو دُنیا کی
کسی کتاب کو دنیا کے کسی اور فرد کے متعلق حاصل نہیں ہے.اور اس کی صحت بھی اس پائے کی ہے کہ دوست
تو دوست کسی بدترین دشمن کو بھی اس کے متعلق حرف گیری کی جرات نہیں ہو سکتی.تاریخ اسلام کا روایتی ماخذ تاریخ ابتدائے اسلام اور سیرتِ رسول کے لیے دوسرا بڑا ماخذ وہ
روایات ہیں جو بصورت حدیث یا تفسیر یا سیرت و مغازی ابتدائے
اسلام میں ایک منظم سلسلہ روایت کے ذریعہ صحابہ سے تابعین تک اور تابعین سے نتبع تابعین تک اور
تبع تابعین سے ان کے بعد آنے والے لوگوں تک پہنچیں اور پھر باقاعدہ کتابوں کی صورت میں ضبط تحریر
میں آکر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں.اس ذخیرہ کا پایہ بھی دوسری اُمتوں کی تاریخ کے مقابلہ پر بہت بلند
ہے.اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی تھی جس نے اپنے اخلاص
اور جوش محبت میں آپ کی ہر حرکت و سکون کا نظر غور کے ساتھ مطالعہ کیا اور اپنی عدیم المثال قلمی مصوری
ل : لائف آف محمد دیبا چه صفحه ۲۶
: ”عرب کی ادبی تاریخ ، صفحہ ۱۴۳
Page 26
11
میں آپ کی ایک ایسی کامل و مکمل تصویر پیچھے چھوڑی کہ جس کے کمال کی نظیر دنیا کی کسی اور تصویر میں نظر نہیں
آتی.حدیث میں صحابہ کے اقوال پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح صحرائے عرب کے ان
ناخواندہ بادیہ نشینوں نے اپنے آقا وسردار کی ہر حرکت و سکون کو لوح تاریخ پر ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے اور کس طرح جاگتے تھے.کس طرح کھاتے تھے اور کس
طرح پیتے تھے.کس طرح اُٹھتے تھے اور کس طرح بیٹھتے تھے اور کس طرح چلتے تھے اور کس طرح کھڑے
ہوتے تھے.کس طرح بولتے تھے اور کس طرح خاموش رہتے تھے.کس طرح ہنتے تھے اور کس طرح روتے
تھے.کس طرح خوش ہوتے تھے اور کس طرح ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے.کس طرح گھر میں رہتے تھے
اور کس طرح سفر میں وقت گزارتے تھے.کس طرح بیویوں سے ملتے تھے اور کس طرح بچوں سے ہمکلام
ہوتے تھے.کس طرح عزیزوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور کس طرح غیروں کے ساتھ معاملہ رکھتے
تھے.کس طرح دوستی نبھاتے تھے اور کس طرح دشمنوں کے ساتھ پیش آتے تھے.کس طرح صلح میں کام
کرتے تھے اور کس طرح جنگ میں لڑتے تھے.کس طرح بندوں کا حق ادا کرتے اور کس طرح خُدا کا حق
بجالاتے تھے.کس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے اور کس طرح اسے لوگوں تک پہنچاتے تھے.غرض آپ کی
زندگی کی تصویر کا ہر پہلو اپنی پوری پوری تفصیل میں اور اپنے باریک در بار یک خط و خال کے ساتھ ہمارے
سامنے محفوظ ہے.حدیث کی کسی کتاب کو ہاتھ میں لے کر اس کی ورق گردانی کریں اس کے ہر صفحہ پر آپ
کی تصویر کا کوئی نہ کوئی پہلو زندگی کی اصل آب و تاب میں چمکتا ہوا نظر آئے گا.اور یوں محسوس ہوگا کہ ایک
جیتی جاگتی تصویر اپنی پوری دلکشی کے ساتھ ہمارے سامنے آکھڑی ہوئی ہے.روایت کا طریقہ اس جگہ غیر مسلم ناظرین کی واقفیت کے لیے یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ
روایت بیان کرنے کا طریق مسلمانوں میں اس طرح رائج تھا کہ نیچے کے راوی
سے شروع ہو کر درجہ بدرجہ ہر راوی کا نام لیتے ہوئے اوپر کو چلتے جاتے تھے حتی کہ روایت آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے کسی صحابی پر جا کر ختم ہو جاتی تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والی
روایت حدیث کہلاتی ہے اور صحابی تک پہنچ کر ختم ہو جانے والی روایت اثر کہلاتی ہے.اور ان میں سے
ہر ایک کی بہت سی صورتیں ہیں.طریق بیان عموماً یوں ہوتا تھا کہ :.مجھ سے الف نے بیان کیا اور الف
نے سب سے سنا تھا.اور سب سے نت نے روایت کی تھی اور ت کو حج نے خبر دی تھی کہ ایک مجلس میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے فلاں امر کے متعلق یہ الفاظ بیان فرمائے تھے یا یہ کہ
Page 27
۱۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے سامنے یہ یہ واقعہ پیش آیا تھا وغیر ذالک.روایت کا یہ ایک
بہت سادہ سا نقشہ ہے، ورنہ عملاً بیان کرنے کے کئی طریقے تھے اور فن اصولِ حدیث کے علماء نے ہر طریق
کے متعلق مفصل بحث کر کے ان کے مدارج قائم کر دیئے ہیں.بہر حال طریق روایت کی تفصیلی صورت جو
بھی ہو یہ ایک ایسا محفوظ طریقہ ہے جس سے ہر روایت کی قدرومنزلت اس کے ہر درجہ پر جانچی جاسکتی ہے
اور دلکشی کے لحاظ سے بھی اس میں ایک ایسا ذاتی عصر داخل ہے کہ جس سے نہ صرف وہ مجلس جس میں کوئی
روایت بالآ خر بیان کی گئی تھی بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی جس سے روایت کا آغاز ہوتا
ہے ایک زندہ تصویر کے طور پر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے.جیسا کہ اس مضمون کے شروع میں بیان کیا گیا ہے روایت کا یہ علم قبل از اسلام زمانہ میں بھی عربوں
میں ایک حد تک رائج تھا ، مگر اسلام میں آکر وہ ایک نہایت منظم اور سائنٹیفک علم بن گیا جس کی امداد کے
لیے کئی ضمنی علوم کی ایجاد بھی وقوع میں آئی.اس جگہ اس علم کی ساری تفصیلات کے بیان کرنے کی تو گنجائش
نہیں، مگر مختصر طور پر اس علم کا ڈھانچہ بصورت ذیل سمجھا جا سکتا ہے.روایت و درایت کے اصول اصل الاصول اس
علم کا یہ ہے کہ ہر واقعہ کی صحت دوطریق پر آزمائی
جاسکتی ہے اور جب تک ان دونوں طریق سے کسی واقعہ کی صحت
پایہ ثبوت کو نہ پہنچ جاوے اس پر پورا اعتماد نہیں کیا جاسکتا.پہلا طریق روایت ہے.یعنی یہ دیکھنا کہ جو
واقعہ ہم تک پہنچا ہے، اس کی صحت کے متعلق بیرونی شہادت کیسی میسر ہے یعنی جس واسطہ سے وہ ہم تک
پہنچا ہے وہ واسطہ کس حد تک قابل اعتماد ہے.دوسرا طریق درایت ہے یعنی یہ دیکھنا کہ واقعہ کی صحت کے
متعلق اندرونی شہادت کیسی موجود ہے.یعنی قطع نظر واسطہ کے کیا وہ واقعہ اپنی ذات میں اور اپنے ماحول کی
نسبت سے ایسا ہے کہ اُسے درست اور صحیح یقین کیا جائے.یہ وہ دو بنیادی اصول ہیں جو مسلمانوں نے
اپنے ہر روایتی اور تاریخی علم کی پڑتال کے لیے ایجاد کئے.اور ابتدائے اسلام سے ان کا اس پر عمل رہا
ہے.ان ہر دو اصول کے ماتحت بہت سے قابلِ لحاظ اُمور قرار دیئے گئے ہیں جن میں سے زیادہ معروف
امور کو ہم اپنے الفاظ میں درج ذیل کرتے ہیں :
-1
روایت کے اصول کے ماتحت یہ باتیں زیادہ قابل لحاظ قرار دی گئی ہیں :
راوی معروف الحال ہو.را وی صادق القول اور دیانت دار ہو.-۲
Page 28
۱۳
بات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو.۴.اس کا حافظہ اچھا ہو.-1
-^
-9.- 1.-1
-۲
اُسے مبالغہ کرنے یا خلاصہ نکال کر رپورٹ کرنے یا روایت میں کسی اور طرح تصرف کرنے کی
عادت نہ ہو.روایت بیان کردہ میں راوی کا کوئی اپنا ذاتی تعلق نہ ہو جس کی وجہ سے یہ خیال کیا جا سکے کہ اس کی
روایت متاثر ہوسکتی ہے.دو او پر نیچے کے راویوں کا آپس میں ملنا زمانہ یا حالات کے لحاظ سے قابلِ تسلیم ہو.روایت کی تمام کڑیاں محفوظ ہوں اور کوئی راوی اوپر سے یا درمیان سے یا نیچے سے چھٹا ہوا نہ ہو.مذکورہ بالا اوصاف کے ماتحت کسی روایت کے راوی جتنے زیادہ معتبر اور قابل اعتماد ہوں گے اتنی
ہی وہ روایت زیادہ پختہ سبھی جائے گی.اسی طرح ایک روایت کے متعلق معتبر راویوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ روایت زیادہ
مضبوط قرار دی جائے گی.درایت کے اصول کے ماتحت مندرجہ ذیل امور زیادہ قابل لحاظ سمجھے گئے ہیں:
روایت کسی معتبر اور مستند عصری ریکارڈ کے خلاف نہ ہو.اس اصل کے ماتحت ہر روایت جو قرآن
شریف کے خلاف ہے قابل رڈ ہوگی.کسی مسلمہ اور ثابت شدہ حقیقت کے خلاف نہ ہو.- کسی دوسری مضبوط تر روایت کے خلاف نہ ہو.-۴
کسی ایسے واقعہ کے متعلق نہ ہو کہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کے دیکھنے یا سننے والوں کی تعداد یقیناً زیادہ
ہونی چاہئے لیکن پھر بھی اس کا راوی ایک ہی ہو.روایت میں کوئی اور ایسی بات نہ ہو جو اسے عقلاً یقینی طور پر غلط یا مشتبہ قرار دیتی ہوئے
درایت کے متعلق بعض ابتدائی مثالیں یہ وہ اصول ہیں جو مسلمان محققین نے اپنی روایات
کی چھان بین کے لیے آغاز اسلام میں مقرر کئے اور
ان اصول کے لیے دیکھو فتح المغیث مصنفہ حافظ زین الدین عبدالرحیم ابن الحسین العراقی اور
موضوعات کبیر مصنفہ ملا علی بن محمد سلطان قاری اور مقدمہ ابن صلاح وغیرہ.
Page 29
۱۴
مسلمان
انہی کے مطابق وہ اپنی روایات کی تحقیق و تدقیق کرتے رہے ہیں.اور ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ روایات کی
پڑتال کے لیے ان سے بڑھ کر کوئی کسوٹی نہیں ہو سکتی.ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں لازماً ہر
مسلمان محدث یا مؤرخ کے پیش نظر رہی ہیں مگر اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہوسکتا کہ یہ وہ اصول ہیں جو
محققین نے ابتدائے اسلام میں اپنی روایات کی تحقیق کے لیے وضع کئے اور جنہیں وہ بالعموم اپنی
تصانیف میں ملحوظ رکھتے رہے ہیں.یہ ممکن ہے کہ ذاتی میلان کی وجہ سے ایک محقق کسی بات کو زیادہ وزن
دیتا ہو اور دوسرا کسی اور کو یا کوئی مصنف اپنے مجموعہ کو زیادہ جامع بنانے کے لیے یا بعض روایات کی امکانی
صحت کے خیال سے کمزور روایتوں کو بھی لے لیتا ہو یا کوئی مصنف ایسے ہی غیر محتاط ہو، کیونکہ کسی طبقہ کے
سب لوگ ایک درجہ کے نہیں ہوتے مگر بہر حال روایت و درایت دونوں کے اصول کو ابتدائی مسلمانوں نے
بالعموم اپنے مد نظر رکھا ہے اور زیادہ محتاط مصنفین پوری تختی کے ساتھ ان پر کار بندر ہے ہیں.روایت کے
اصول کے متعلق تو ہمیں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلامی تحقیق کا یہ پہلو دوست و دشمن سب
کے نزدیک مسلم ہے؛ البتہ چونکہ بعض مغربی محققین نے جن میں سرولیم میور بھی شامل ہیں اس خیال کا اظہار
کیا ہے کہ مسلمانوں نے درایت کے پہلو کو مد نظر نہیں رکھا اور صرف روایت کے اصول کے ماتحت اپنی
روایتوں کی پڑتال کرتے رہے ہیں یا اس لیے درایت کے پہلو کے متعلق اس جگہ بعض مثالیں درج کی
جاتی ہیں تاکہ ناظرین کو اس بات کا اندازہ کرنے کا موقع ملے کہ یہ اعتراض کس قدر غلط اور بے بنیاد ہے.سب سے پہلے خود قرآن شریف اس بات کو پیش کرتا ہے کہ محض روایت پر بنیاد رکھنا ہر صورت میں
کافی نہیں بلکہ کسی خبر کو صحیح سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کے متعلق اچھی طرح تحقیق کر
لی جائے.چنانچہ فرماتا ہے:
إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا
د یعنی اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تویہ دیکھ لیا کرو کہ خبر لانے والا کیسا آدمی ہے.پھر اگر
یہ راوی قابلِ اعتماد نہ ہو تو اچھی طرح سارے پہلوؤں پر نظر ڈال کر سوچ لیا کرو.“
اس آیت سے گو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف روایت کی صحت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مگر غور
کرنے سے یہ بات مخفی نہیں رہتی کہ دراصل یہ آیت روایت و درایت دونوں پہلوؤں کی حامل ہے؛
چنانچہ فاسق کے لفظ میں تو روایت کے پہلو کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ دیکھ لیا کرو کہ خبر لانے والا کیسا
ے دیکھو لائف آف محمد مصنفه سرولیم میورد یا چه xxxviii
الحجرات آیت نمبرے
Page 30
۱۵
ہے اور تبینوا کے لفظ میں درایت کا پہلو مد نظر ہے یعنی دوسری جہت سے بھی خبر کی اچھی طرح چھان بین
کرلیا کرو.پھر فرماتا ہے:
إِنَّ الَّذِينَ جَاءَ وَ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ
ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا
يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظِيمُ
د یعنی جو لوگ رسُولِ خُدا کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے خلاف بہتان لگانے میں شریک
ہوئے ہیں وہ اے مسلمانو ! تمہیں میں سے ایک پارٹی ہیں مگر تمہیں چاہئے تھا کہ آپس میں ایک
دوسرے کے متعلق نیک گمان کرتے.پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے اس بہتان کو سنتے ہی یہ
کہدیا کہ خدا تعالیٰ پاک و بے عیب ہے.یہ تو ایک صاف بہتان نظر آتا ہے.“
ان آیات میں صراحت کے ساتھ درایت کے اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ صحابہ کو اس بات
پر تو سیخ کی گئی ہے کہ خواہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے والے بظاہر مسلمان ہی تھے، مگر جب تم حضرت عائشہ
کے حالات سے اچھی طرح آگاہ تھے اور تم جانتے تھے کہ وہ خدائے پاک کے رسول کی بیوی اور دن رات
آپ کی صحبت میں رہنے والی ہے تو تمہیں چاہئے تھا کہ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اس خبر کو سنتے ہی
بہتان اور افتراء قرار دے کر ٹھکرا دیتے.گویا اس آیت میں ضمنا یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک روایت کے
متعلق صرف یہ دیکھ کر کہ اس کے راوی بظاہر اچھے لوگ ہیں اسے نہیں مان لینا چاہئے بلکہ خدا داد عقل کے
ماتحت دوسری باتیں بھی دیکھنی ضروری ہیں.اور اگر دوسری با تیں روایت کومشتبہ قرار دیں تو اسے قبول نہیں
کرنا چاہئے.اسی قرآنی اصل کے ماتحت حدیث میں بھی یہ تاکید آتی ہے کہ محض کسی بات کو سُن کر اسے سچا نہیں سمجھ
لینا چاہئے بلکہ ہر جہت سے تحقیق کر کے معلوم کرنا چاہئے کہ حقیقت کیا ہے؛ چنانچہ حدیث میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ :
كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ *
لے سورۃ نور آیت نمبر ۱۲ تا ۱۷
صحیح مسلم جلدا بابِ النَّهَى عَنِ الْحَدِيثِ
Page 31
۱۶
یعنی ایک انسان کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے اسے
بلا تحقیق آگے روایت کرنا شروع کر دے
اس حدیث میں گوروایتی تحقیق کی طرف بھی اشارہ ہے، مگر اصل مقصود درایتی تحقیق ہے جیسا کہ
بِكُلِّ مَا سَمِعَ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں.یعنی محض کسی بات کائننا اس کے قبول کیے جانے کا باعث نہیں
بننا چاہئے بلکہ دوسری جہات سے بھی غور کرنا چاہئے کہ آیا جو خبر ہمیں پہنچی ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں ، بلکہ
اس حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو شخص تحقیق کرنے کے بغیر یونہی ہر سنی سنائی بات آگے روایت
کر دیتا ہے وہ جھوٹ کی اشاعت کا ایسا ہی ذمہ دار ہے جیسا کہ جھوٹ بولنے والا شخص.الغرض قرآن شریف و حدیث دونوں اس اصول کو بیان کرتے ہیں کہ ہر خبر کی تصدیق کے متعلق
روایت و درایت دونوں پہلو مد نظر رہنے چاہئیں ، چنانچہ اس اصل کے ماتحت حدیث میں کثرت کے ساتھ
ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ اور ان کے بعد آنے والے مسلمان محققین نے ہمیشہ روایت کے پہلو کے ساتھ
درایت کے پہلو کو بھی مدِ نظر رکھا ہے اور بسا اوقات روایتی لحاظ سے ایک روایت کے مضبوط ہونے کے
باوجو د درایت کی بنا پر اسے رڈ کر دیا ہے.مثلاً حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوُضُوءُ مِمَّا
مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ انَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ اَنَتَوَضَّأُ مِنَ
الْحَمِيمِ.....فَقَالَ أَبُو عِيسَى وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَرَكِ الْوُضُوءِ
د یعنی ایک مجلس میں ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ
جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس کے استعمال سے وضو ضروری ہو جاتا ہے.اس پر ابن عباس
نے ابو ہریرہ کو ٹوک کر کہا کہ کیا پھر ہم گھی یا تیل کے استعمال کے بعد بھی وضو کیا کریں.اور کیا ہم
گرم پانی کے استعمال کے بعد بھی وضو کیا کریں؟ یہ روایت درج کر کے ترمذی علیہ الرحمۃ بیان
کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ آگ پر تیار کی ہوئی چیز کے
استعمال سے وضوضروری نہیں ہو جاتا.اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تک کی روایت کو جن کی روایات کی تعدا د سارے صحابہ
سے زیادہ ہے حضرت ابن عباس نے اس عقلی دلیل سے رڈ کر دیا کہ اول تو محض آگ پر کسی چیز کا تیار ہونا
ترمذى كتاب الطهارة باب مَاغَيَّرَتِ النَّارُ
Page 32
اس بات سے کوئی جوڑ نہیں رکھتا کہ اس کے استعمال سے وضوضروری ہو جائے.دوسرے یہ کہ جب دین کی
بنائیر اور آسانی پر ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول کس طرح منسوب ہو سکتا ہے کہ بس
جس چیز کو بھی آگ چھو جائے اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے اور اسی لیے با وجو د حضرت ابو ہریرہ کی اس
صریح حدیث کے اکثر ائمہ حدیث وفقہ کا یہی مذہب ہے کہ آگ والی چیز کے استعمال سے وضو واجب نہیں
ہوتا.اور بعض دوسری حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے.اس کا یہ مطلب نہیں
کہ نعوذ باللہ حضرت ابنِ
عباس یا بعد کے ائمہ حدیث کے نزدیک ابو ہریرہ نے جو روایت بیان کی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد تو ہے ، مگر وہ قابلِ عمل نہیں.بلکہ مطلب یہ ہے کہ ابنِ عباس اور دوسرے محققین کے نزدیک اس
روایت میں ابو ہریرہ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا آپ کا ارشاد بعض خاص قسم کے حالات کے متعلق ہو گا جسے
ابو ہریرہ نے عام سمجھ کر اُسے وسعت دے لی.بہر حال باوجود اس کے کہ اصول روایت کے لحاظ سے یہ
حدیث بالکل صحیح قرار پاتی ہے، مسلمان محققین نے درایت کی بنا پر اسے صحیح تسلیم نہیں کیا.اور جب ابو ہریرہ
جیسے گہنہ مشق راوی کی روایت درایت کی جرح سے محفوظ نہیں سمجھی گئی تو میور صاحب کے اس قول کی حقیقت
ظاہر ہے کہ مسلمان صرف روایتی پہلو کو دیکھ کر ہر بات کو صحیح مان لیا کرتے تھے اور درایت کو کام میں نہیں
لاتے تھے.پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ.....فَحَدَّتْ الشَّعْبِيُّ
بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلُ
لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ثُمَّ اَخَذَ الأَسْوَدُ كَفَّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ
وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا ، قَالَ عُمَرُ لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ اَوْنَسِيَتْ
یعنی ابو اسحاق سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں ایک مجلس میں اسود بن یزید کے ساتھ
بیٹھا تھا کہ شعمی نے یہ روایت بیان کی کہ فاطمہ بنت قیس صحابیہ بیان کرتی ہے کہ جب اس کے
خاوند نے اُسے طلاق دے دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکان اور خرچ نہیں
دلایا.اس پر اسود نے ایک کنکروں کی میٹھی اُٹھا کر شعمی کو ماری اور کہا کیا تم یہ حدیث بیان کرتے
مسلم كتاب الطلاق باب المطلقه البائن لا نفقة لها -
Page 33
۱۸
ہو؟ حالانکہ حضرت عمرؓ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک
عورت کے بیان پر قرآن اور سنت رسول کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ نہیں معلوم کہ اصل بات کیا تھی
اور اس نے کیا سمجھا ، یا اصل بات کیا تھی اور اسے کیا یا درہا.“
اس حدیث میں گویا حضرت
عمر خلیفہ ثانی ایک صحابیہ کی روایت کو اس بنا پر رڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کی
رائے میں قرآنی تعلیم اور سنت رسول کے خلاف ہے اور اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہوگا اُسے یا تو وہ کبھی نہیں ہوگی یا بعد میں بھول گئی ہوگی.بہر حال حضرت عمرؓ نے
درایت کی بنا پر ایک روایتی لحاظ سے صحیح حدیث کو رد کر دیا اور جمہور اسلام کا یہی فتویٰ ہے کہ فاطمہ کی
روایت غلط تھی اور حضرت عمرؓ کا خیال درست ہے.پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے:
عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ سَمِعَ عُتُبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْصَارِى يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَالِكَ وَجُهُ اللهِ قَالَ مَحْمُودُ فَحَدَّثْتُهَا قَوْمًا فِيهِمُ
أبُو أَيُّوبَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْكَرَ هَا عَلَيَّ اَبُوْ أَيُّوبَ
وَقَالَ وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتُ قَطُّ
یعنی محمود بن الربیع روایت کرتے ہیں کہ میں نے عتبان بن مالک سے یہ سُنا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہوئی
ہے جو سچی نیت سے خدا کی رضا کی خاطر لا إِلهَ إِلَّا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن جب میں نے
یہ روایت ایک ایسی مجلس میں بیان کی جس میں ابوایوب انصاری صحابی بھی موجود تھے تو ابوایوب
نے اس روایت سے انکار کیا اور کہا خدا کی قسم! میں ہرگز نہیں خیال کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہو.“
اس حدیث میں حضرت ابوایوب انصاری نے ایک ایسی حدیث کو جو اصول روایت کے لحاظ سے صحیح
تھی اپنی درایت کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا.اور گو یہ ممکن ہے کہ حضرت ابوایوب کا استدلال
درست نہ ہو مگر بہر حال یہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ صحابہ یونہی کو رانہ طور پر ہر روایت کو
: بخاری ابواب التطوع باب صلوة النوافل جماعة
Page 34
۱۹
قبول نہیں کر لیتے تھے، بلکہ درایت و روایت ہر دو کے اصول کے ماتحت پوری تحقیق کر لینے کے بعد قبول
کرتے تھے.پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرُتُ ذَالِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ
اللهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَاحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذِّبُ
بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَلَكِنْ قَالَ إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَسْبُكُمُ الْقُرآنُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
دو یعنی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ یہ روایت بیان کرتے تھے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے.ابنِ عباس کہتے ہیں
کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد میں نے یہ حدیث حضرت عائشہ سے بیان کی تو فرمانے لگیں.اللہ تعالیٰ عمرہ پر رحم فرمائے.خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہر گز نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا
تھا کہ ایک کافر کے مرنے کے بعد اگر اس کے ورثاء اس پر روئیں تو اس وجہ سے اس کا عذاب
اور زیادہ ہو جاتا ہے.( کیونکہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے اس فعل میں ان کا مؤید ہوا کرتا تھا )
اور پھر حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ ہمیں قرآن کا یہ قول کافی ہے کہ کوئی نفس دوسرے نفس کا بوجھ
نہیں اُٹھا سکتا.“
اس حدیث سے بھی درایت کے پہلو کا استعمال نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے یعنی حضرت عائشہ نے
حضرت عمر جیسے جلیل القدر انسان کی روایت کو صرف ایک بالمقابل روایت بیان کر دینے سے ہی رڈ نہیں کیا
بلکہ ساتھ ہی اپنے خیال میں اس کے غلط ہونے کی قرآن شریف سے ایک دلیل بھی دی.ہمیں اس جگہ اس
بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا حضرت عائشہ کا خیال درست تھا یا کہ حضرت عمرؓ کا.صرف یہ
ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ الزام بالکل غلط ہے کہ مسلمان محققین صرف ایک روایت کو سُن کر اسے قبول کر لیتے
تھے.کیونکہ حق یہ ہے کہ وہ پوری طرح درایت کو کام میں لاتے اور ہر چیز کو اپنی عقل خدا داد کے ساتھ تول کر
پھر قبول کرتے تھے اور اس بنا پر بعض اکابر صحابہ تک میں باہم اختلاف ہو جاتا تھا.بخاری و مسلم بحواله مشکوة باب الْبُكَاءِ على الميت -
Page 35
درایت کے کمزور پہلو یہ چار مثالیں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں اور جو صرف نمونہ کے طور پر درج کی
گئی ہیں ورنہ اس
قسم کی مثالیں اسلامی تاریخ میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی
ہیں.ان میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے چار جلیل القدر صحابیوں کے فعل سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے
کہ ابتدائے اسلام سے ہی درایت کا پہلو روایت کے پہلو کے ساتھ ساتھ چلا آیا ہے اور مسلمان محققین
پوری دیانتداری اور آزادی کے ساتھ درایت کے اصول کو اپنی روایات کی تحقیق اور پڑتال میں استعمال
کرتے رہے ہیں اور اسی قسم کی مثالیں بعد کے زمانوں کے متعلق بھی پیش کی جاسکتی ہیں.مگر ہم اپنے اس
مضمون کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایک عقلمند انسان کے لیے اس قدر کافی ہے.بہر حال میور صاحب
اور ان کے ہم عقیدہ اصحاب کا یہ اعتراض بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ مسلمان محققین صرف روایت کے
پہلو کود یکھتے تھے اور درایت سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا.ہاں اگر ہمارے معترضین کا یہ منشاء ہے کہ ہر حال
میں درایت کے پہلو کو ترجیح اور غلبہ ہونا چاہئے اور خواہ ایک بات اصول روایت کے لحاظ سے کیسی ہی پختہ
اور مضبوط ہو وہ اگر درایت کے پہلو کے لحاظ سے مشکوک نظر آتی ہے تو بہر صورت اسے رد کر دینا چاہئے تو یہ
خیال نہ صرف بالکل غلط ہے بلکہ علمی ترقی کے لیے بھی سخت مضر اور نقصان دہ ہے.درایت خواہ کیسی ہی
اچھی چیز ہومگر اس کے ساتھ دو خطر ناک کمزوریاں بھی لگی ہوئی ہیں.اول یہ کہ اس کا تعلق استدلال کے
ساتھ ہوتا ہے اور استدلال ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اختلاف رائے کی بہت گنجائش ہے.دوسرے یہ
کہ درایت کی بنا زیادہ تر انسان کے سابقہ تجربہ اور معلومات پر ہوتی ہے اور تجربہ اور معلومات ایسی چیزیں
ہیں کہ روز بدلتی رہتی ہیں کیونکہ ان میں ہر وقت وسعت اور ترقی کی گنجائش ہے.ان وجوہ کی بنا پر درایت
کے پہلو پر زیادہ بھروسہ کرنا اپنے اندر ایسے خطرات رکھتا ہے جنہیں کوئی دانا شخص نظر انداز نہیں کرسکتا.مثلاً
ایک شخص کسی روایت کو قرآن شریف کی کسی آیت کے خلاف سمجھ کر رڈ کر دیتا ہے مگر ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرا
شخص اُسے کسی قرآنی آیت کے خلاف نہ پائے بلکہ وہ دونوں کی ایسی تشریح کر دے کہ ان کے درمیان کوئی
تضاد نہ رہے.یا مثلاً ایک شخص ایک روایت کو کسی ثابت شدہ حقیقت کے خلاف سمجھتا ہے ،مگر ہو سکتا ہے کہ
ایک دوسرے شخص کے نزدیک وہ چیز جسے ایک ثابت شدہ حقیقت سمجھا گیا ہے وہ ثابت شدہ حقیقت نہ ہو.یا ایک شخص ایک روایت کو انسانی تجربہ اور مشاہدہ کے خلاف سمجھتا ہے ،مگر ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرا شخص جس
کا تجربہ اور مشاہدہ زیادہ وسیع ہے وہ اسے اس کے خلاف نہ سمجھے وغیر ذالک.ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ
درایت کے پہلو پر زیادہ زور دینا نہ صرف اصولاً غلط ہے، بلکہ علمی ترقی کے لئے بھی ایک بہت بھاری روک
Page 36
۲۱
ہے اور اس پر زیادہ زور دینا انہی لوگوں کا کام ہے جو اپنے محدود علم اور محدود تجربہ اور محمد و مشاہدہ اور محدود
استدلال سے ساری دنیا اور سارے زمانوں کے علم کو ناپنا چاہتے ہیں.اور ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ نظریہ دنیا
کی علمی ترقی کے لئے ایک سم قاتل سے کم نہیں.اگر ابتدائی مسلمان محدث یا مؤرخ درایت پر اس قدر زور
دیتے جتنا میور صاحب اور ان کے ہم عقیدہ اصحاب چاہتے ہیں کہ دینا چاہئے تھا تو یقیناً بانی اسلام کے
متعلق بہت سے مفید معلومات کا ذخیرہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا، کیونکہ اس صورت میں ان میں سے کوئی
مصنف کسی بات کو اور کوئی کسی کو اپنی درایت کے خلاف پا کر ترک کر دیا حالانکہ بالکل ممکن ہے کہ وہ صحیح
درایت کے خلاف نہ ہوتیں؛ چنانچہ ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ کئی باتیں جو گذشتہ زمانوں میں سمجھ نہیں آتی تھیں
آج ان کا سمجھنا آسان ہو رہا ہے.پس پختہ اور صحیح اصول وہی تھا جو ابتدائی مسلمان مصنفین نے اختیار کیا
کہ انہوں نے اصل بنیا د روایت کے اصول پر رکھی مگر روایت کی مدد کے لئے ایک حد تک درایت کو بھی
کام میں لاتے رہے.اور اس طرح انہوں نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لئے ایک عمدہ ذخیرہ روایات
کا جمع کر دیا.اور اب یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ روایت و درایت کے اصول کے مطابق اس ذخیرہ کی
چھان بین کر کے صحیح کو ستقیم سے جدا کر لیں.روایات کا قلمبند ہونا گو اصول روایت کے لحاظ سے کسی روایت کا لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے اور
گواصول
اسلامی روایات میں ایک بڑا حصہ ایسی روایتوں کا شامل ہے جو کم از کم ابتداء
میں صرف زبانی طور پر سینہ بہ سینہ مروی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابتدائے
اسلام سے ہی بعض راویوں کا یہ طریق رہا ہے کہ جو حدیث بھی وہ سنتے تھے یا جو روایت بھی ان تک پہنچتی تھی
اسے وہ فوراً لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے اور جب کسی کو آگے روایت سُناتے تھے تو اس لکھی ہوئی یادداشت سے
پڑھ کر سناتے تھے جس سے ان روایات کو مزید مضبوطی حاصل ہو جاتی تھی.اس قسم کے لوگ صحابہ کرام میں
بھی پائے جاتے تھے اور بعد میں بھی.بلکہ بعد میں جوں جوں علم ترقی کرتا گیا اور فن تحریر زیادہ پھیلتا گیا،
ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی.حتی کہ اس زمانہ میں آکر جب کہ روایات کتابی صورت میں جمع ہونے
لگیں اور موجودہ کتب حدیث وغیرہ کے مجموعے عالم وجود میں آنے شروع ہوئے جس کا آغاز دوسری
صدی ہجری سے سمجھا جا سکتا ہے روایات کو لکھ کر محفوظ کر لینے کا طریق عام طور پر رائج ہو چکا تھا اور راوی
لوگ اپنی روایات کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے اپنی تحریری یا داشتوں سے کثرت کے ساتھ مدد لینے لگ
گئے تھے لیکن چونکہ محض کسی تحریری یادداشتوں کا موجود ہونا اسے قابل سند نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کی
Page 37
تائید میں معتبر زبانی تصدیق بھی موجود نہ ہو اور اسی لیے آج تک ہر مہذب ملک کی عدالتوں میں ہر دستاویز
کی تصدیق کے لئے زبانی شہادت ضروری قرار دی جاتی ہے اس لئے بالعموم محد ثین نے زبانی اور تحریری
روایت کے امتیاز کو اپنے مجموعوں میں ظاہر نہیں کیا.لیکن اس میں ہر گز کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ اب جو
احادیث کے مجموعے ہمارے سامنے ہیں ان سب میں ایک معتد بہ حصہ ایسی روایتوں کا شامل ہے جو زبانی
انتقال کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر بھی ایک راوی سے دوسرے راوی تک منتقل ہوتی ہوئی نیچے اتری ہیں.اس دعوی کی تصدیق میں ہم اس جگہ اختصار کی غرض سے صرف صحابہ کے زمانہ کی چند مثالیں درج کریں
گے کیونکہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ خود صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث اور روایات کو لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے اور پھر اُسی مجموعہ سے آگے سلسلہ روایت چلاتے تھے تو یہ
ایک قطعی ثبوت اس بات کا ہوگا کہ یہ طریق بعد کے زمانہ میں (جب کہ فن تحریر بہت زیادہ وسیع ہو گیا اور
روایات کے لکھنے کے لئے ہر قسم کی سہولت میسر آ گئی ) بدرجہ اولی جاری رہا.سب سے پہلی اور اصولی
حدیث ہم اس معاملہ میں وہ درج کرنا چاہتے ہیں جن میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریک
فرمائی ہے کہ جس شخص کو میری باتیں یاد نہ رہتی ہوں اسے چاہئیے کہ انہیں لکھ کر محفوظ کر لیا کرے؛ چنانچہ
تر ندی میں یہ روایت آتی ہے کہ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ الْحَدِيث وَلَا يَحْفَظُهُ فَشَكَا ذَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ وَاَوْ مَأْ بِيَدِهِ لِلْخَطِ
یعنی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاری شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! میں آپ کی باتیں سنتا ہوں مگر مجھے وہ یاد نہیں رہتیں.آپ نے فرمایا: تم اپنے دائیں ہاتھ کی مدد حاصل کر کے میری باتوں کو لکھ لیا کرو.“
اس حدیث سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تحریک فرمایا
کرتے تھے کہ جس شخص کو میری باتیں یاد نہ رہتی ہوں ، وہ انہیں لکھ کر محفوظ کر لیا کرے اور آپ کے اس
فرمان کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں تاریخ میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر نظر نہ بھی آوے کہ فلاں فلاں صحابی
حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے تو بھی قیاس یہی ہوگا کہ بعض صحابی ضروری حدیثیں لکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ ممکن
ا : ترمذی ابواب العلم باب ماجاء في الرخصة فيه
Page 38
۲۳
نہیں ہوسکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت سے صحابہ جیسی جماعت میں سے کسی فرد نے بھی
فائدہ نہ اٹھایا ہو اور بہر حال جس صحابی کو آپ نے براہ راست مخاطب کر کے یہ الفاظ فرمائے تھے اس نے تو
ضرور اس ارشاد کی تعمیل کی ہوگی.مگر یہ صرف قیاس ہی نہیں ہے بلکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر
آتا ہے کہ بعض صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے؛ چنانچہ روایت آتی ہے کہ
عبد اللہ بن عمر و بن العاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی سنتے تھے وہ لکھ لیا کرتے
تھے.اس پر بعض لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غصہ میں
ہوتے ہیں، تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو.یہ ٹھیک نہیں ہے.عبداللہ بن عمرو نے اس پر لکھنا چھوڑ دیا، لیکن
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا :
اكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ
نکلتا ہے.یعنی تم بے شک لکھا کرو کیونکہ خدا کی قسم میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق اور راست
اس کے بعد عبد اللہ بن عمر و آپ کی باتیں لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے ؛ چنانچہ بخاری میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ
أكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنّي إِلَّا مَا كَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ
وَلَا اكْتُبُ
د یعنی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی مجھ سے
زیادہ حدیث محفوظ نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمرو کے کیونکہ ان کی عادت تھی کہ حدیث سُن کر
لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا.“
پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٌّ هَلْ عِنْدَ كُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ
اللهِ اَوْ فَهُمْ أعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اَوْ مَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلتُ مَا فِي هَذِهِ
الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْآسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ -
: ابو داؤد کتاب العلم باب كتابة العلم
: بخاری کتاب العلم باب كتابة العلم
: بخاری کتاب العلم باب كتابة العلم
Page 39
۲۴
یعنی ابو جحیفۃ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت علی سے یہ دریافت کیا
کہ کیا آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا بھی ہے.اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ سوائے قرآن شریف
کے اور کچھ نہیں.ہاں ایک مسلمان کی خداداد عقل ہے جس سے وہ خودسوچ کر اور قیاس کر کے
فتویٰ معلوم کر سکتا ہے؛ البتہ میرے پاس یہ ایک لکھا ہوا صحیفہ ضرور موجود ہے.میں نے پوچھا
اس صحیفہ میں کیا ہے.فرمانے لگے اس میں فلاں فلاں مسئلہ کے متعلق چند حدیثیں لکھی ہیں.“
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا بھی یہی طریق تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خاص خاص باتوں
کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے.پھر ایک اور حدیث آتی ہے کہ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ
فَقَالَ....فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَكْتُبُ لِي فَقَالَ أَكْتُبُوا لَابِي
فُلان
د یعنی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک خطبہ دیا.جس میں یہ یہ کچھ فرمایا.اس پر ایک یمنی شخص نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول
اللہ! یہ خطبہ مجھے لکھ دیجئے.آپ نے حکم دیا کہ وہ خطبہ اُسے لکھ کر دے دیا جائے.“
ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ صحابہ کے زمانہ سے ہی حدیثوں کے لکھنے کا رواج شروع ہو چکا تھا.اور
بعض صحابہ اس پر کار بند تھے اور یقیناً اس کے بعد جوں جوں زمانہ گذرتا گیا حدیثوں کو لکھ کر محفوظ کر لینے کا
رواج زیادہ ہوتا گیا مگر جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں اس مختصر نوٹ میں بعد کے زمانہ کی مثالیں درج کرنے
کی گنجائش نہیں ؛ البتہ صرف اس اظہار کے لئے کہ بعد میں حدیثوں کے قلمبند کرنے کے طریق میں کس
قدر وسعت ہو گئی تھی اس جگہ صرف ایک مثال پر اکتفا کی جاتی ہے.یحیی بن معین ایک مشہور را وی گذرے
ہیں جن سے امام بخاری اور امام مسلم اور ابوداؤد سجستانی وغیرہ بڑے بڑے محدثین نے روایت لی ہے ان
کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ اُن کے پاس چھ لاکھ حدیث لکھی ہوئی محفوظ تھی جس سے وہ آگے روایت کیا
کرتے تھے؛ چنانچہ وفیات الاعیان میں لکھا ہے کہ:
سُئِلَ يَحْيَى كَمُ كَتَبْتَ مِنَ الْحَدِيثِ فَقَالَ كَتَبْتُ بِيَدِي هَذِهِ سِتَّ
مِائَةِ أَلْفِ حَدِيث
: بخاری کتاب العلم باب كتابة العلم : وقيات الاعيان مصنفه ابن خلكان حالات یحیٰ بن معین
Page 40
۲۵
در یعنی یحیی بن معین سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے
کتنی حدیثیں لکھی ہیں.انہوں نے
جواب دیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے چھ لاکھ حدیث لکھی ہے.“
یہ یا درکھنا چاہئے کہ یحییٰ بن معین جامعین حدیث میں سے نہیں ہیں.جنہوں نے امام بخاری اور مسلم
وغیرہ کی طرح کوئی مجموعہ حدیث پیچھے چھوڑا ہو بلکہ ان کا حدیث لکھنا صرف ایک راوی کی حیثیت میں تھا.اسی پر دوسرے رُواۃ حدیث کا قیاس ہو سکتا ہے.الغرض اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ صحابہ کے زمانہ سے ہی احادیث و روایات کا ضبط تحریر
میں آنا شروع ہو چکا تھا اور بعد میں یہ سلسلہ زیادہ وسیع ہوتا گیا حتی کہ احادیث کے موجودہ مجموعوں میں
ایک معتد بہ حصہ ایسی روایتوں کا موجود ہے جو زبانی روایتوں کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر بھی مروی ہوتی
ہوئی جامعین حدیث تک پہنچی ہیں.ہمارا یہ مطلب نہیں کہ اکثر صحابہ حدیث لکھنے کے عادی تھے یا یہ کہ بعد
کے راوی سب کے سب لازماً حدیث لکھ لیا کرتے تھے.ایسا دعویٰ یقیناً واقعات کے خلاف ہوگا، بلکہ غرض
صرف یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی بعض نے حدیث لکھنے کا طریق شروع کر دیا تھا
اور بعد کے زمانہ میں یہ طریق زیادہ وسیع ہو گیا گو پھر بھی یقیناً احادیث کا ایک معتد بہ حصہ زبانی روایت پر
ہی بنی رہا ہے اور موجودہ مجموعوں میں ہر دو قسم کی روایات شامل ہیں.اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض حدیثوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان ہوا ہے
کہ میری طرف منسوب کر کے سوائے قرآن شریف کے اور کچھ نہ لکھا کر ویا اور اس سے بعض لوگوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ صحابہ حدیث نہیں لکھتے ہوں گے.اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو واقعات کے مقابل پر
کوئی استدلال قابل قبول نہیں ہو سکتا.جب واقعہ یہ ہے کہ بعض صحابہ حدیث لکھا کرتے تھے تو کوئی
استدلالی دلیل اس کے مقابل پر کیا وزن رکھ سکتی ہے.علاوہ ازیں ان احادیث کی حقیقت کے متعلق جن
میں لکھنے سے منع کیا گیا ہے غور نہیں کیا گیا.دراصل یہ احادیث خاص زمانہ اور خاص حالات کے متعلق ہیں
اور صرف ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے اور اس حکم سے
غرض یہ تھی کہ تا قرآنی وحی کے ساتھ کوئی دوسری چیز مخلوط نہ ہونے پائے.عام لوگوں کے لئے یا عام
حالات میں کوئی روک نہیں تھی.واللہ اعلم.لے : مثلا دیکھو مسلم اور ترمذی وغیرہ
Page 41
۲۶
حدیث وسیرۃ کی روایتوں میں ایک بنیادی فرق اس اصولی بحث کے ختم کرنے سے
قبل یہ
ذکر بھی ضروری ہے کہ گو مسلمان مصنفین
نے اپنی روایات کی پڑتال میں روایت و درایت ہر دو قسم کے اصول کو علی قدر مراتب ملحوظ رکھا ہے مگر انہوں
نے ہر قسم کی روایت کے لئے ایک ہی معیار نہیں رکھا بلکہ وہ ایک دانشمند محقق کی طرح اس غرض وغایت کے
مناسب حال جس کے لئے کوئی روایت مطلوب ہوتی تھی اپنے معیار کو نرم یا سخت کرتے رہے ہیں.یعنی
بعض علوم میں انہوں نے اپنا معیار سخت رکھا ہے اور بعض میں نرم.مثلاً حدیث میں جہاں عقائد و اعمال کا
تعلق تھا محد ثین نے بڑی سختی کیسا تھ روایات کو پرکھا ہے اور اپنے معیار کو بہت بلند رکھا ہے لیکن
سیرۃ و تاریخ وغیرہ میں اتنی سختی نہیں کی ، چنانچہ علامہ علی بن برہان الدین حلبی اپنی سیرۃ میں لکھتے ہیں کہ :
لَا يَخْفى أَنَّ السِّيرَ تَجْمَعُ الصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ وَالْمُرُ سَلَ
وَالْمُنقَطِعَ
و یعنی یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ سیرۃ کی روایتوں میں صحیح اور ضعیف اور مرسل اور
منقطع سبھی قسم کی روایتیں شامل ہیں.“
اور پھر امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ حدیث کی زبانی اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ :
إِذَا رَوَيْنَا فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَدَدْ نَاوَ إِذَارَوَيْنَا فِي الْفَضَائِلِ
وَنَحْوَهَا تَسَاهَلُنَا
یعنی ہمارا اصول یہ ہے کہ جب ہم حلال و حرام کے مسائل کے لئے کوئی روایت بیان
کرتے ہیں تو ہم اس کی تحقیق میں بڑی سختی سے کام لیتے ہیں.لیکن فضائل اور سیرۃ میں اپنے
معیار کو نرم کر دیتے ہیں.“
اور اس اصول کی مزید تشریح یوں کرتے ہیں کہ :
الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ التَّرَخْصُ فِي الرَّقَائِقِ وَمَا لَا
حُكُم فِيهِ مِنْ اَخْبَارِ الْمَغَازِى وَمَا يَجْرِى مَجْرَى ذَالِكَ وَ إِنَّهُ يُقْبَلُ فِي
الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لِعَدْمِ تَعَلُّقِ الْأَحْكَامِ بِهَا -
یعنی اکثر اہل علم نے یہی طریق رکھا ہے کہ ایسی باتیں جن میں شرعی احکام نہ بیان ہوں
ل : سيرة حلبیہ جلد ا صفحه ا
: سيرة حلبیہ جلد ا صفحه ا
: سيرة حلبیہ جلد ا صفحه ا
Page 42
۲۷
جیسے سیرۃ مغازی وغیرہ اُن میں اپنے معیار کو نرم رکھنا چاہئے ، کیونکہ ان امور میں ہم ایسی
روایتوں
کو بھی قبول کر سکتے ہیں جنہیں دینی اور فقہی احکام کے معاملہ میں قبول نہیں کر سکتے.“
امام احمد بن حنبل نے اس اصول
کی تشریح میں ایک لطیف مثال بھی بیان کی ہے؛ چنانچہ فرماتے ہیں:
إِبْنُ إِسْحَاقَ رَجُلٌ نَكْتُبُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَعْنِي الْمَغَازِي وَنَحْوَهَا وَ
إِذَا جَاءَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ أَرَدْنَا قَوْمًا هَكَذَاوَ قَبِضَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ الْأَرْبَعِ
یعنی ابن اسحاق صاحب سیرۃ و مغازی بے شک اس رتبہ کے آدمی ہیں کہ ہمیں ان سے
سيرة و تاریخ میں روایت لیتے ہوئے تامل نہیں ہونا چاہئے ،لیکن جب حلال وحرام کے مسائل کا
سوال ہو تو ہمیں ایسے آدمی چاہئیں.یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چار انگلیاں
مضبوطی کے ساتھ ملا کر باہم جفت کرلیں.جس سے مراد یہ تھی کہ حدیث میں ایسے راوی درکار
ہیں جن میں کوئی رخنہ نہ نکالا جا سکے.“
الغرض حدیث وسیرۃ کی روایتوں کے معیار میں ہمیشہ سے ایک اصولی فرق مد نظر رکھا گیا ہے اور یہی
ہونا چاہئے تھا، کیونکہ حدیث میں جس کی روایت نے دین کی بنیاد بنا تھا سخت معیار رکھنا ضروری تھا تا کہ
کوئی کمز ور روایت حدیث کے ذخیرہ میں راہ پا کر دینی فتنہ کا باعث نہ بنے، لیکن سیرۃ و تاریخ میں یہ پہلوایا
خطر ناک نہیں تھا.بلکہ سیرۃ و تاریخ میں زیادہ قابل توجہ یہ بات تھی کہ اساسی مواد جمع ہو جائے جس میں بعد
میں اصول مقررہ کے ماتحت چھان بین کی جاسکے.یہی وجہ ہے کہ اسلامی کتب حدیث کا روایتی پہلو کتب
سيرة ومغازی وغیرہ کی نسبت بہت زیادہ مضبوط اور بلند سمجھا گیا ہے.مگر یہ کوئی نقص نہیں ہے بلکہ ایسا ہی
ہونا چاہئے تھا تا کہ جہاں ایک طرف دین کو فتنہ و اختلاف سے بچایا جاتا وہاں تاریخ میں جامعیت قائم
رہتی.خوب سوچ لو کہ تاریخ کے لئے یہی پالیسی مناسب تھی.سوائے اس کے کہ کوئی روایت بالبداہت
غلط اور باطل ہو ہر وہ روایت لے لی جاوے تا کہ بعد کی تحقیق اور ریسرچ کے لئے ایک بنیادی ذخیرہ محفوظ
ہو جائے مگر حدیث کے لئے یہ پالیسی سخت نقصان دہ تھی، کیونکہ اس کے لئے ضروری تھا کہ معیار کو ایسا سخت
رکھا جائے کہ خواہ کوئی مضبوط روایت گر جائے مگر بہر حال جو حدیث لی جائے وہ پختہ اور قابلِ اعتماد ہو.اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احادیث کا سارا مجموعہ غلطی سے پاک ہے یا یہ کہ سیرت و تاریخ کا مجموعہ کمزور
روایات پر مبنی ہے بلکہ غرض صرف یہ ہے کہ بالعموم حدیث کا معیار سیرۃ و تاریخ سے بالا و بلند ہے.اور اسی
: فتح المغيث صفحہ ۱۳۰
Page 43
۲۸
لیے مسلمان مؤرخین میں سے جو لوگ زیادہ محقق گذرے ہیں انہوں نے سیرۃ و تاریخ کے واقعات کے لئے
ان روایات کو ترجیح دی ہے جو دینی مسائل کے ضمن میں کتب حدیث میں مروی ہوتی ہیں.اور مصنف
کتاب ہذا کا بھی اس تصنیف میں یہی مسلک رہا ہے.کتب اصول حدیث روایت کا جو علم مسلمانوں نے ایجاد کیا جس کے اندر اصول روایت و درایت
دونوں شامل ہیں وہ عموماً علم اصولِ حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے.اس علم کے متعلق بہت سی تصنیفات پائی جاتی ہیں جن میں متقدمین اور متاخرین ہر دو کی تصانیف شامل
ہیں مگر آجکل جو کتب اس فن میں زیادہ معروف و متداول ہیں جن میں اکثر متقدمین کی تحریرات کا خلاصہ
آگیا ہے وہ یہ ہیں :
-1
-۲
علوم الحديث المعروف بمقد مہ ابن صلاح مصنفہ حافظ ابو عمر و عثمان بن عبدالرحمن المعروف بابن
صلاح المتوفی ۶۴۳ ھ.فتح المغيث فی اصول الحدیث مصنفہ حافظ زین الدین عبدالرحیم بن الحسین العراقی المتوفی ۸۰۵ ھ.شرح الفیة العراقی فی اصول الحدیث مصنفہ محمد بن عبد الرحمن السخاوی المتوفی ۹۰۲ھ.موضوعات کبیر مصنفہ نورالدین ملا علی بن محمد سلطان القاری المتوفی ۱۰۱۶ھ.ان کتب میں روایت و درایت ہر دو کے اصول پوری شرح وبسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اور ہر
پہلو کے متعلق متعدد مثالیں دے دے کر بات کو واضح کیا گیا ہے.مؤخر الذکر کتاب حقیقہ موضوع
روایتوں کے بیان میں ہے مگر ضمنا اصولِ حدیث کی بحث بھی آ جاتی ہے.مصطلحات حدیث
فن اصول حدیث یا علم روایت کے ضمنی علوم میں دو علم خاص طور پر قابل ذکر
ہیں.اعنی علم مصطلحات حدیث اور علم اسماء الرجال.مقدم الذکر علم میں
حدیث کی اصطلاحات کا بیان ہوتا ہے جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مختلف اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں
اور ان کے کیا کیا نام ہیں اور ہر حدیث کی ایک قسم دوسری اقسام کے مقابل پر کیا وزن رکھتی ہے اس علم کے
ماتحت حدیث کی جو اقسام مختلف جہات سے مقرر کی گئی ہیں ، اُن میں سے زیادہ معروف یہ ہیں:
متواتر.مشہور.عزیز.شاذ.منکر صحیح.حسن.ضعیف.متروک.موضوع.مرفوع.موقوف.مقطوع.متصل.منقطع.معلق.مرسل.معضل.معلل - مدلس.مضطرب.مدرج - قولی فعلی.تقریری.قدسی وغیرہ وغیرہ.
Page 44
۲۹
-1
اس علم میں بھی متعد دکتا ہیں لکھی گئی ہیں جن میں اس وقت زیادہ معروف و متداول یہ ہیں :
نُزهة النظر في توضيح نخبة الفكر مصنفہ ابوالفضل احمد ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ.اليواقيت والدرر مصنفه شیخ عبدالرؤف المنادی المتوفی ۱۰۳۱ھ.اسماء الرجال فن اسماء الرجال اس علم کا نام ہے جس میں حدیث و سیرت وغیرہ کے راویوں کے
حالات زندگی کو تنقیدی نظر کے نیچے لا کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے تا کہ جب بھی کوئی
روایت سامنے آوے تو اس کے سلسلہ رواۃ کا امتحان کیا جاسکے.اس سے ظاہر ہے کہ یہ علم بہت وسیع
اور پھیلا ہوا ہے حتی کہ بقول سرولیم میور اس علم کے ذریعہ چالیس ہزار راویوں کے حالات زندگی ضبط میں
آگئے ہیں.جو یقیناً دنیا کی تاریخ میں ایک بے نظیر ریکارڈ ہے.یہ مجموعہ سرسری حالات کا ذخیرہ نہیں ہے
بلکہ صحیح تنقیدی اصول کے مطابق تیار کیا گیا ہے.جس میں ہر راوی کی تاریخ ولادت ، تاریخ وفات،
جائے رہائش، حالات زندگی، عادات و اطوار، علمی قابلیت ، ذہن ، حافظہ اور سمجھ ، دیانت وامانت،
طریق روایت کی خصوصیات ، استادوں کے نام، شاگردوں کے نام ، ہمعصروں کے نام وغیرہ وغیرہ پوری
صحت اور تعیین کے ساتھ درج کئے گئے ہیں..سب سے پہلا شخص جس نے اس علم کی طرف با قاعدہ فن کے رنگ میں توجہ کی وہ شعبہ بن الحجاج
المتوفی ۱۶۰ ھ تھے.ان کے بعد امام یحیی بن سعید القطان المتوفی ۱۹۸ ھ نے اس علم کو اور ترقی دی اور سب
سے پہلا مجموعہ تیار کیا.بعدہ علامہ احمد بن عبداللہ امجلی المتوفی ۲۶۱ ھ نے اور امام عبدالرحمن بن ابی حاتم
الرازی المتوفی ۳۲۷ ھ نے اس فن میں مفید کتابیں لکھیں اور ہر دو نے اپنی تصانیف کا نام کتاب الجرح و
التعدیل رکھا.مگر اس فن میں متقدمین کی کتب میں سب سے زیادہ جامع اور مستند کتاب الــــــامــل فـي
معرفة الضعفاء و المتروكين مصنفہ ابواحمد عبدالله بن محمد ابن عدی المتوفی ۳۶۵ تھی.ان کے علاوہ
حافظ عقیلی اور امام دارقطنی وغیرہ نے بھی اس فن میں کتابیں لکھی ہیں مگر افسوس ہے کہ ان میں سے اکثر کتب
اب نا پید ہو چکی ہیں گو بعد کی کتب میں ان سب کے کثرت کے ساتھ حوالے آتے ہیں.بعد کی کتب میں سے جو ابتدائی کتب پر مبنی ہیں مندرجہ ذیل کتابیں زیادہ معروف و متداول ہیں :
-1
-۲
الکمال فی معرفۃ الرجال مصنفہ حافظہ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسی المتوفی ۶۰۰ ھ.تہذیب الکمال فی معرفۃ الرجال مصنفہ حافظہ جمال الدین یوسف بن زکی المڑی المتوفی ۲۲-
لی: دیباچہ لائف آف محمد صفحه ۳۸
: کشف الظنون جلد اصفحه ۳۹۱
۷۲۲ھ.
Page 45
-۳
میزان الاعتدال فی نقد الرجال (تین جلد ) مصنفہ حافظ شمس الدین ابوعبد الله حمد بن احمد الذھبی.المتوفی ۷۴۸ھ.تہذیب التہذیب (بارہ جلد ) مصنفہ حافظ ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن علی بن حجر العسقلانی
المتوفی ۸۵۲ھ.-۵- استیعاب فی معرفۃ الاصحاب (۲) جلد ) مصنفہ حافظ ابو عمرو یوسف بن عبداللہ بن محمد بن
-4
عبدالبر القرطبی المتوفی ۴۶۳ ھ.اسدالغابہ فی معرفۃ الصحابہ (۵) جلد ) مصنفہ حافظ عزالدین ابوالحسن علی بن محمد بن عبدالکریم
المعروف ابن اثیر الجزری المتوفی ۶۳۰ ھ.اصابہ فی معرفۃ الصحابہ (۱۰ جلد ) مصنفہ حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ.یہ بات قابل ذکر ہے کہ اوپر کی فہرست میں مؤخر الذکر تین کتابیں دراصل فن اسماء الرجال سے تعلق
نہیں رکھتیں بلکہ محض صحابہ کے حالات میں ہیں لیکن چونکہ یہ دونوں علوم آپس میں بڑی حد تک ملتے ہیں اس
لئے ہم نے ان کتب کو اس فہرست میں شامل کر لیا ہے.اقسام کے لحاظ سے روایات کا علم تین قسموں میں منقسم ہے.اعنی (۱) حدیث
کتب حدیث
(۲) تفسیر اور (۳) سیرۃ و تاریخ.مؤخر الذکر علم کے ایک حصہ کو مغازی بھی کہتے ہیں.حدیث روایات کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس کی اصل غرض و غایت دینی مسائل کا ضبط ہے خواہ ضمنی طور
پر اس میں تفسیری اور تاریخی حصہ بھی آجاوے.حدیث میں عموماً وہ روایات درج ہوتی ہیں جن کی سند
بالآ خر کسی نہ کسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے.یعنی آخری راوی یہ بیان کرتا ہے کہ میں
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا.یا یوں کرتے دیکھا.یا میرے سامنے آپ کے سامنے
کسی نے یوں کیا اور آپ نے اُسے نہیں روکا.مگر کتب حدیث میں کچھ حصہ ایسی روایات کا بھی آجاتا ہے
جو صرف صحابہ کے اقوال و اعمال تک محدود ہوتا ہے جنہیں اصطلاحی طور پر آثار کہتے ہیں.حدیث کی کتابیں
بے شمار ہیں جو زیادہ تر دوسری اور تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں ، مگر یہ سب ایک درجہ کی نہیں
ہیں.کیونکہ سب محدثین نے ایک ساسخت معیار نہیں رکھا اور نہ ایک سی احتیاط برتی ہے.حدیث کی زیادہ
معروف کتابیں مع ان کے مختصر حالات و کوائف کے درج ذیل کی جاتی ہیں:
Page 46
۳۱
صحیح بخاری مصنفہ امام محمد بن اسمعیل بخاری یہ سب کتب حدیث میں صحیح ترین کتاب سمجھی
۱۹۴ھ تا ۲۵۶ھ گئی ہے.امام بخاری صاحب نے چار لاکھ
روایات کے مجموعہ میں سے صرف چار ہزار
احادیث چن کر اس مجموعہ میں درج کی ہیں
۲ صحیح مسلم
اور انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے.بلا ریب
ان کا معیا رسب محدثین سے بالا وارفع ہے.مصنفہ امام مسلم بن حجاج اس کا درجہ بخاری سے نیچے مگر باقی کتب
۲۰۴ھ تا ۲۶۱ھ حدیث سے اوپر سمجھا جاتا ہے.جس روایت
میں بخاری اور مسلم اتفاق کر لیں اسے متفق علیہ
کہتے ہیں جو سب سے مضبوط
سمجھی جاتی ہے.۳- جامع ترمذی مصنفہ ابو عیسی محمد بن عیسی ترمندی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ساتھ اگلی چار
۲۰۹ھ تا ۲۷۹ھ کتابیں مل کر صحاح ستہ کہلاتی ہیں اور یہ سب
-۴- سنن ابوداؤد مصنفہ ابو داؤد سلیمان بن اشعث معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہیں.ان کا درجہ
۲۰۲ھ تا ۲۷۵ھ قریباً اسی ترتیب کے مطابق سمجھا جاتا ہے جو
۵- سنن نسائی مصنفہ احمد بن شعیب النسائی اس فہرست میں ملحوظ رکھی گئی ہے.-1
ے.۲۱۵ھ تا ۳۰۶ھ
سنن ابن ماجہ مصنفه محمد بن یزید ابن ماجه قزوینی
۲۰۹ھ تا ۲۷۳ھ
موطا امام مالک مصنفه امام مالک ابن انس یہ کتاب بہت بلند پایہ ہے بلکہ بعض نے اسے
۹۵ھ تا ۱۷۹ھ بخاری کے برابر قرار دیا ہے مگر چونکہ اس کے
بیشتر حصہ کا اسلوب فقہ کے طریق پر ہے اس
لیے اسے حدیث کی کتاب کے طور پر صحاح
میں شمار نہیں کیا گیا ورنہ اپنے مرتبہ کے لحاظ
Page 47
سے وہ کسی مجموعہ حدیث سے کم نہیں.امام
مالک فقہ کے ائمہ اربعہ میں سے ہیں.-- مسند امام ابو حنیفہ مصنفه امام نعمان بن ثابت ابوحنیفہ فقہ کے ائمہ اربعہ میں سے سب سے بلند تر
۸۰ تا ۱۵۰ھ ہیں.یہ محدث نہیں تھے اور نہ انہوں نے اس
طرف توجہ کی مگر بعض احادیث اپنی فقہ کی بنیاد
کے لئے جمع کی ہیں.-۹- مسند امام شافعی مصنفہ امام محمد بن ادریس شافعی یہ بھی فقہ کے ائمہ اربعہ میں سے ہیں اور ان کی
۱۰۵ھ تا ۲۰۴ھ کتاب اپنی فقہ کی تائید میں چند احادیث کا
مجموعہ ہے.۱۰- مسند احمد مصنفہ امام احمد بن محمد بن حنبل" یہ بھی فقہ کے ائمہ اربعہ میں سے ہیں مگر ان کی
۱۶۱ھ تا ۲۴۱ھ احادیث کا مجموعہ بھی نہایت شاندار ہے اور
حدیث کی کتابوں میں غالباً سب سے بڑا ہے
مگر صحت روایت کا معیار صحاح کے برابر
نہیں ہے.11- سنن دارمی مصنفہ عبداللہ بن عبد الرحمن صحاح ستہ کے بعد اس کا مرتبہ اچھا ہے.-۱۲
- مجم كبير
واوسط وصغير
دارمی
۱۸۱ھ تا ۲۵۵ھ
مصنفہ سلطان بن احمد طبرانی مشہور محدث ہیں
۲۶۰ھ تا ۳۶۰ھ
سنن دار قطنی مصنفہ علی بن محمد دار قطنی
۳۰۶ھ تا ۳۸۵ھ
-۱۴- مستدرک حاکم مصنفہ ابوعبد الله محمد بن عبد اللہ الحاکم
۳۲۱ھ تا ۴۰۵ھ
Page 48
۳۳
۱۵ متفرق کتب مصنفہ احمد بن حسین بیہقی مشہور محدث ہیں
حديث وسيرة
۳۸۴ھ تا ۴۵۸ھ
مذکورہ بالا محد ثین کے علاوہ بھی ایسے محدث گزرے ہیں جنہوں نے باوجود بُعدِ زمانہ کے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ تک روایت کا سلسلہ پہنچا کر احادیث نقل کی ہیں یا مگر ہم نے
زیادہ معروف محد ثین کے نام بعد کی فہرست میں درج کر دیئے ہیں اور اس فہرست میں بھی مؤخر الذکر
محدثین کے مجموعوں میں کیا بوجہ بعد زمانہ اور کیا بوجہ احتیاط کی کمی کے کمزور اور ضعیف روایات کا حصہ
زیادہ آ گیا ہے، مگر بہر حال حدیث کا یہی مجموعہ ہے جس سے ایک مؤرخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرۃ وسوانح اور آغاز اسلام کی تاریخ کے متعلق علی قدر مراتب فائدہ اُٹھا سکتا ہے اور جیسا کہ اوپر بیان کیا
گیا ہے فی الجملہ احادیث کا مجموعہ سیرت و تاریخ کی روایات سے زیادہ پختہ اور زیادہ قابلِ اعتبار ہے
اور احادیث کی جو اعلیٰ کتابیں ہیں مثلاً بخاری اور مسلم ان کے مقابلہ پر تو سیرۃ کی روایات کی حیثیت بہت
ہی کم ہے.سنت اور حدیث میں فرق حدیث کی بحث ختم کرنے سے پہلے سنت کے متعلق ایک مختصر نوٹ
درج کرنا نا مناسب نہ ہوگا.سو جاننا چاہئے کہ یہ جو عام طور پر خیال
کیا جاتا ہے کہ حدیث اور سنت ہم معنی الفاظ ہیں ، یہ درست نہیں ہے بلکہ حق یہ ہے کہ حدیث اور سنت
دو مختلف چیزیں ہیں کیونکہ جہاں حدیث ان لفظی روایات کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اقوال وافعال کے متعلق صحابہ سے تابعین تک اور تابعین سے تبع تابعین تک اور تبع تابعین سے ان کی
بعد کی نسل تک پہنچیں اور پھر ائمہ حدیث کی تحقیق و تدقیق کے بعد کتابی صورت میں جمع ہو گئیں وہاں
سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یعنی تعامل کا نام ہے جو کسی لفظی روایت کے ذریعہ نہیں بلکہ
مسلمانوں کے متحدہ تعامل کے ذریعہ ایک نسل سے دوسری نسل تک اور دوسری سے تیسری تک اور تیسری
سے چوتھی تک پہنچا ہے اور علی ہذا القیاس.مثلاً قرآن شریف میں نماز کا حکم ہے اور اب قطع نظر اس کے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل کے متعلق کوئی زبانی ہدایات دی تھیں یا نہیں آپ نے
ے : مثلاً ابن حبان.سعید بن منصور ابن ابی شیبہ.عبدالرزاق.ابو یعلی.ابن عدی عقیلی.خطیب بغدادی.ہزار.ابن عساکر.ابن ابی حاتم.ابن مردویہ وغیرہ وغیرہ.ان میں سے بعض مؤرخ بھی ہیں.
Page 49
۳۴
صحابہ کے سامنے اپنے عمل سے اس کی ساری تفصیلات کر کے دکھا دیں اور عمر بھر اس تعامل کو تکرار کے
ساتھ دُہراڈ ہرا کر ان کے ذہن نشین کرا دیا اور خود اپنی نگرانی میں ان کو نماز کی تفصیلات پر قائم کر دیا
اور پھر صحابہ کے ذریعہ یہ تعامل تابعین تک پہنچا.جنہوں نے صحابہ کی کسی زبانی تشریح سے نہیں بلکہ عملی
تعامل سے اس کو صحابہ سے سیکھا اور اسی طرح یہ سلسلہ نیچے چلتا چلا گیا.اسی طرح دوسرے مسائل کا حال
ہے.اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کی اصل بنیاد قرآن شریف اور سنت پر ہے جو ابتداء سے ہی ایک
دوسرے کے پہلو بہ پہلو چلے آئے ہیں اور حدیث صرف ایک زائد چیز ہے جو علمی تشریح یا ضمنی تائید
وغیرہ کے لئے کام آ سکتی ہے ورنہ اس پر اسلام کی اصل بنیاد نہیں ہے، لیکن غلطی سے بعض لوگوں نے
حدیث اور سنت کو ایک ہی چیز سمجھ رکھا ہے.اس بحث کو ہمارے اس مضمون کے ساتھ تعلق نہیں ہے.مگر ہم نے خیال کیا کہ حدیث کے متعلق اس عام غلط فہمی کو اس جگہ دُور کر دیا جائے تا کہ نا واقف لوگوں
کے دلوں میں یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ گویا اسلام کی بنیاد ایک ایسی چیز پر ہے جو ڈیڑھ دوسو سال بعد ضبط میں
آئی ہے.كتب تفسیر روایات کا دوسرا مجموعہ روایتی تفسیر سے تعلق رکھتا ہے.اس میں چونکہ قرآن شریف کی
تشریح کا تعلق ہے جو زیادہ تر علمی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اس علم میں بھی حدیث کے
برابر احتیاط نہیں برتی گئی.مگر بہر حال یہ بھی ایک مفید مجموعہ ہے جس کے متعلقہ حصوں سے سیرۃ و تاریخ کی
تدوین میں فائدہ اُٹھایا جا سکتا ہے.اس سلسلہ کی زیادہ معروف کتابیں جن میں منقولی اور روایتی طریق پر
قرآن شریف کی تفسیر درج کی گئی ہے یہ ہیں :
-1
تفسیر ابن جریر
مصنفہ امام ابو جعفر محمد بن جریر منقولی تفسیر میں یہ سب سے جامع
۲۰ جلد)
الطبرى
مجموعہ ہے ، مگر اس مجموعہ میں کمزور
۲۲۴ھ تا ۳۱۰ھ روایات بھی شامل ہو گئی ہیں.-۲- تفسیر ابن کثیر مصنفہ حافظ عمادالدین اسمعیل بن یہ تفسیر نہایت معتبر اور مستند سمجھی جاتی
عمر ابن کثیر ہے جس کے متعلق علامہ زرقانی کا
(۱۰ جلد )
۷۰۰ تا ۷۷۴
قول ہے کہ اس جیسی اور کوئی تفسیر نہیں
لکھی گئی.
Page 50
۳۵
الدر المخور فى مصنفہ شیخ جلال الدین یہ بعد کی تصنیف ہے جس میں
التفسیر بالماثور (۶) جلد عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی رطب و یابس سب کچھ جمع ہو گیا
)
۸۴۹ھ تا ۹۱۱ھ
ہے.سیرت و تاریخ کی ابتدائی کتب تیسر ا سلسلہ سیرۃ و تاریخ و مغازی کا ہے.اس سلسلہ کی غرض و
غایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات وسوانح اور
ابتدائی اسلامی جنگوں اور ابتدائی اسلامی تاریخ کے متعلق روایات جمع کرنا تھی مگر جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا
ہے یہ روایتیں بحیثیت مجموعی حدیث کی روایتوں سے کمزور ہیں کیونکہ اس سلسلہ کے جمع کرنے والوں کی
غرض سیرت و تاریخ کے سارے مواد کو ایک جگہ جمع کر دینا تھی تا کہ کوئی بات ضبط میں آنے سے رہ نہ جائے
اور پھر بعد میں آنے والے اس کی چھان بین خود کر لیں جو قرآن شریف اور صحیح احادیث کو سامنے رکھ کر
مشکل نہیں ہے.اس سلسلہ کی ابتدائی تصنیفات جن میں ہم نے جغرافیہ اور تاریخ عرب کی کتب بھی شامل
کر لی ہیں یہ ہیں :
کتاب المغازی مصنفہ محمد بن مسلم بن یہ کتاب غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
شہاب زہری حالات زندگی اور ابتدائی جنگوں کی تاریخ میں
-1
۵۱ھ تا ۱۲۴ھ سب سے پہلی تصنیف ہے.امام زھری تابعین
میں سے تھے اور متعدد صحابہ کو دیکھا اور ان
کی باتوں کو سُنا تھا.نہایت ثقہ اور وسیع العلم
انسان تھے مگر افسوس کہ ان کی کتاب اب ناپید
ہو چکی ہے.البتہ بعض کتابوں میں اس کے
حوالے آتے ہیں اور امام زہری کی زبانی روایات
تو اکثر کتابوں میں آتی ہیں اور نہایت معتبر خیال
کی جاتی ہیں.٢- المغازی مصنفہ موسی بن عقبہ موسیٰ بن عقبہ امام زھری کے شاگردان رشید میں
المتوفی ۱۴۱ھ سے تھے اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا.نہایت محتاط
مصنف تھے اور جو کچھ لیتے تھے جانچ تول کر لیتے
Page 51
۳۶
تھے.حدیث میں امام مالک ان کے شاگرد تھے ،
مگر افسوس کہ ان کی کتاب بھی نا پید ہے.۳- سیرۃ ابن اسحاق مصنفہ محمد بن اسحاق ابن اسحاق بھی امام زھری کے شاگردوں میں
المتوفی ۱۵۱ھ سے تھے اور سیرۃ میں بڑا پایہ رکھتے ہیں.ان کی
کتاب سیرۃ و مغازی میں بطور بنیاد کے سمجھی گئی
ہے اور اکثر بعد کے مؤرخین ان کے خوشہ چین
ہیں.بعض لوگوں نے ان کی ثقاہت پر شبہ کیا ہے
مگر یہ درست نہیں ؛ البتہ چونکہ اُن کا طبعی میلان
سیرۃ کی طرف تھا.اس لئے حدیث کے سخت
معیار کے مطابق وہ پورے نہیں اتر تے.اسی
لیے امام بخاری نے حدیث میں ان سے روایت
نہیں لی لیکن تاریخ میں آزادی سے لی ہے.ان
کی کتاب عام طور پر نہیں ملتی لیکن ابن ہشام
کی سیرۃ میں اس کا بیشتر حصہ اس طرح آگیا
ہے کہ اصل کتاب کی چنداں ضرورت نہیں
رہتی.-۴- سیرۃ ابن ہشام مصنفہ عبدالمالک بن ہشام یہ بہت پایہ کے مؤرخ تھے اور نہایت ثقہ سمجھے
المتوفی ۲۱۳ھ جاتے ہیں.ان کی سیرت جو بیشتر طور پر سیرت
ابن اسحاق پر مبنی ہے.بہت جامع اور مکمل تصنیف
ہے.سیرت کی کتابوں میں ان کی سیرت سب
سے زیادہ مقبول و متعارف ہے.-۵ کتاب السيرة و مصنفہ محمد بن عمر الواقدی یہ صاحب بہت وسیع المعلومات مؤرخ تھے.مگر
کتاب المغازی
۱۳۰ھ تا ۲۰۷ھ
چونکہ جھوٹ سچ اور صحیح وسقیم میں کوئی پر ہیز نہیں تھا
Page 52
۳۷
اس لئے اکثر محققین کے نزیک ان کی تصنیفات
بالکل نا قابلِ اعتبار اور نا قابل سند مجھی گئی ہیں ان
کے متعلق ہم ایک علیحدہ نوٹ دیں گے.۶- طبقات كبير مصنفہ محمد ابن سعد ابن سعد ، واقدی کے خاص شاگردوں میں سے
تھے اور ان کے سیکرٹری بھی تھے مگر باوجود اس
-2
۱۲۸ھ تا ۲۳۰ھ
نسبت کے خود ثقہ اور معتبر سمجھے گئے ہیں ان کی
کتاب بارہ جلدوں میں ہے اور بہت تفصیلی
معلومات کا ذخیرہ ہے.پہلی دو جلدیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں ہیں
اور باقی آپ کے صحابہ کے حالات میں.اگر
واقدی کی روایتوں کو الگ کر دیا جائے تو یہ کتاب
بہت اچھی اور مستند ہے.تاریخ الامم مصنفہ ابو جعفر محمد ابن جریر یہ کتاب سیرة کی کتاب نہیں بلکہ تاریخ کی کتاب
والملوک
الطبرى
ہے، مگر چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرة
۲۲۴ھ تا ۳۱۰ھ بھی اس کے اندر شامل ہے، اس لئے اسے سیرت
کی کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے.طبر کی اسلام کے
مشہور مستند علماء میں سے تھے اور ان کی کتاب جو
بارہ جلدوں میں ہے نہایت جامع تاریخ سمجھی
گئی ہے.انہوں نے ابن اسحاق اور واقدی اور
ابن سعد کی بیشتر روایتوں کو جمع کرنے کے علاوہ
بہت سی نئی روایتیں بھی درج کی ہیں اور سیرت و
تاریخ میں ایک نہایت عمدہ ذخیرہ اپنے پیچھے
چھوڑا ہے.
Page 53
- شمائل ترمذی مصنفہ ابو عیسی محمد بن ترندی کی حدیث کا ذکر حدیث کی ذیل میں گذر
عیسی ترمذی چکا ہے، مگر انہوں نے شمائل نبوی پر ایک علیحدہ
۲۰۹ھ تا ۲۷۹ھ رسالہ بھی لکھا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
حلیہ مبارک اور ذاتی عادات و خصائل میں ایک
مختصر مگر عمدہ تصنیف ہے.۹ - كتاب المعارف مصنفہ عبداللہ بن یہ کتاب تاریخ عرب اور اسلام کے متعلق
مسلم بن قتیبہ معلومات عامہ پر مشتمل ہے جس میں آنحضرت
۲۱۳ تا ۲۷۶ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص خاص
اصحاب کے حالات بھی درج ہیں.۱۰ - فتوح البلدان مصنفہ ابو جعفر احمد بن یحیی بن اس کتاب میں اُن فتوحات کا ذکر ہے جو
جابر البلاذری.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء کے
-11
المتوفی ۲۷۹ھ ہاتھ پر ہوئیں.مشہور اور متداول کتاب ہے.-۱ کتاب الخراج مصنفہ قاضی ابو یوسف ابو یوسف مشہور فقیہ گذرے ہیں.امام ابو حنیفہ
یعقوب بن ابراہیم کے خاص شاگردوں میں سے تھے.اس کتاب
المتوفی ۱۸۲ھ میں انہوں نے ان ٹیکسوں وغیرہ کے مسائل اور
تاریخ بیان کی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے خلفاء کی طرف سے مفتوح قبائل پر
لگائے جاتے تھے.۱۲- مروج الذہب مصنفہ ابوالحسن علی بن حسین اس کتاب میں دنیا کی مختلف اقوام وممالک کی
مسعودی
تاریخ سے ابتداء کر کے بالآ خر عرب کے حالات
المتوفی ۵۳۴۶ درج کرتے ہوئے خلفائے بنو عباس تک اسلامی
تاریخ کو مکمل کیا گیا ہے.۱۳- تاریخ مکه مصنفہ ابوالولید محمد بن مکہ کی مستند اور ابتدائی تاریخ ہے.عبدالکریم از رقی.المتوفی ۲۲۳ھ
Page 54
۳۹
ا صفة جزيرة العرب مصنفہ ابومحمد حسن بن احمد بن جغرافیہ عرب کی ابتدائی اور مستند کتاب ہے.یعقوب الہمدانی المعروف
بابن حائک المتوفی ۳۳۴ھ
یہ وہ ذخیرہ ہے جو تاریخی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ابتدائی اسلامی تاریخ کا
اصل ماخذ اور منبع ہے اور بعد کی سب کتابیں اسی منبع کی خوشہ چین ہیں، لیکن جیسا کہ او پر ظاہر کر دیا گیا ہے
یہ سب کتب سیرت کی کتابیں نہیں اور نہ ہی صحیح معنی میں وہ سب کی سب تاریخ کی کتابیں ہیں مگر چونکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آغاز اسلام کی تاریخ کے ساتھ ان کتب کے مضامین کو ایک طبعی جوڑ ہے،اس
لیے ہم نے انہیں سیرۃ کی کتابوں میں شامل کر لیا ہے.باقی جیسا کہ اوپر اشارہ کر دیا گیا ہے خالص سیرت
کی اصل ابتدائی کتا بیں جو اس وقت پائی جاتی ہیں ، وہ صرف چار ہیں.اعنی سیرت ابن ہشام.کتاب
السیرت والمغازی لواقدی.طبقات ابن سعد اور تاریخ طبری.لیکن ان میں سے چونکہ واقدی مطعون و
متروک ہے، اس لئے عملاً ما خذ صرف تین رہ جاتے ہیں.یعنی ابن ہشام.ابنِ سعد اور طبری.اور اس میں
شبہ نہیں کہ قرآن وحدیث کو چھوڑ کر سیرت کی حقیقی بنیا د نہیں تین کتابوں پر ہے.واقدی کے متعلق ایک مختصر نوٹ واقدی کے متعلق ہمیں کچھ علیحدہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی
لیکن بدقسمتی سے یورپین مصنفین نے اسے اتنا نوازا ہے کہ
اس کی حقیقت کے اظہار کے لئے ایک علیحدہ نوٹ ضروری ہو گیا ہے.جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے،
واقدی کا زمانہ ۱۳۰ھ سے لے کر ۲۰۷ ھ تک تھا اور اس میں شبہ نہیں کہ زمانہ کے لحاظ سے وہ کسی دوسرے
مؤرخ سے کم محفوظ پوزیشن میں نہیں تھا.مگر یہ بات کسی شخص کے ذاتی صفات و عادات کا رُخ بدل نہیں سکتی
اور حقیقت یہ ہے کہ واقدی اپنی وسعت علم کے باوجود ایک بالکل نا قابلِ اعتبار اور غیر ثقہ شخص تھا اور محققین
نے اسے بالا تفاق جھوٹا اور دروغ گو قرار دیا ہے.اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری روایتیں غلط
اور جھوٹی ہوتی تھیں.دُنیا میں جھوٹے سے جھوٹا انسان بھی ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ حق یہ ہے کہ ایک
جھوٹے آدمی کی بھی اکثر باتیں کچی اور واقعہ کے مطابق ہوتی ہیں.لیکن دوسری طرف اس بات میں بھی
ہرگز کوئی طبہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہو اس کی کوئی بات بھی قابل حجت نہیں رہتی.لے : اس مصنف کی ایک کتاب اکلیل بھی ہے جو دس جلدوں میں ہے اور قبیلہ میر کے حالات اور تاریخ یمن کے علاوہ بہت
سے دوسرے مفید معلومات پر مشتمل ہے.دیکھو کشف الظنون زمیر نام اکلیل.
Page 55
واقدی کے متعلق یہ مسلم ہے کہ وہ ایک بہت عالم انسان تھا اور اس کے تاریخی معلومات اتنے وسیع تھے کہ
اس زمانہ میں کسی اور مؤرخ کے کم ہوں گے.مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وسعت معلومات نے ہی اس
کے سر کو پھرا دیا تھا کہ وہ کسی بات کے متعلق لاعلمی کا اظہار کرنے کی بجائے خود اپنی طرف سے بات بنا کر
بیان کر دیا کرتا تھا، چنانچہ اس کے متعلق ایک محقق کا یہ بہت اچھا مقولہ ہے کہ اگر واقدی سچا ہے تو بے نظیر
ہے.اور اگر جھوٹا ہے تو تب بھی عدیم المثال ہے.مگر بد قسمتی سے واقدی کی یہی طلاقت لسان اور یہی
وسعت علم ہمارے یورپین مصنفین کو اس کا دلدادہ بنا رہی ہے.انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ واقد کی سچا
تھا یا جھوٹا.اس کی عادت ایک محتاط محدث کی طرح تحقیق کر کے بات کرنے کی تھی یا کہ یونہی واہی تباہی
کہتے جانے کی.ان کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ واقد کی جو کچھ کہتا ہے تفصیل سے کہتا ہے اور یوں کہتا
ہے جیسے کوئی شخص پاس بیٹھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا ہو.اگر اس کا کوئی قول کسی صحیح اور مضبوط روایت کے
خلاف ہے تو ہوا کرے اُن کے لئے سب روایتیں برابر ہیں اور سوائے اپنے دماغ کی شہادت کے اور کوئی
شہادت قابل قبول نہیں.مسلمان محققین نے جو اپنی عمریں کھپا کھپا کر ہر روایت سے بال کی کھال نکالی ہے
اور ہر راوی کے صحیح صحیح حالات معلوم کر کے علم روایت کے لئے ایک سچا تر از و مہیا کر دیا ہے اہلِ مغرب کو
اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے.بہر حال ہم کسی کے قلم اور زبان کو تو روک نہیں سکتے مگر ہم بتا دینا چاہتے ہیں
کہ واقدی کے متعلق ان مسلمان محققین نے جن کی دیانت و امانت اور اصابت رائے کو سب نے تسلیم کیا
ہے کیا رائے دی ہے:
نام رائے دہندہ الفاظ جن میں رائے کا
اظہار کیا گیا ہے
ترجمہ اردو
امام احمد بن حنبل هُوَ كَذَّابٌ يُقَلِبُ واقدی ایک پرلے درجہ کا جھوٹ بولنے والا شخص
علیہ الرحمة
الحديث
۱۶۱ھ تا ۲۴۱ھ
ہے جور وایتوں
کو بگاڑ بگاڑ کر بیان کرتا ہے.ابواحمد عبد اللہ بن محمد أَحَادِيْتُهُ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ واقدی کی روایتیں قابلِ اعتبار نہیں ہیں اور یہ
المعروف بابن عدى وَالْبَلاءُ مِنْهُ خرابی خود اس کے نفس کی طرف سے ہے.۲۷۷ھ تا ۳۲۵ھ
تہذیب التہذیب حالات واقدی
Page 56
۴۱
ابو حاتم محمد بن ادریس يَضَعُ الْحَدِيثَ واقدی اپنے پاس سے جھوٹی حدیثیں بنا بنا کر بیان
۱۹۵ھ تا ۲۷۷ھ
کیا کرتا تھا.علی بن عبد الله بن يَضَعُ الْحَدِيثَ لَا اَرْضَاهُ واقدی جھوٹی روایتیں بناتا تھا میرے نزدیک وہ
جعفر المعروف بابن فِي شَيْءٍ
المدینی
۱۶۱ھ تا ۲۲۴ھ
امام علی بن محمد دار قطنی فِيهِ ضُعْفٌ
۳۰۶ تا ۳۸۵
کسی جہت سے بھی قابل قبول نہیں.واقدی کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں.اسحاق بن ابراہیم هُوَ عِنْدِي مِمَّنْ يَضَعُ میرے نزدیک واقدی جھوٹی روایتیں گھڑنے
المعروف بابن الْحَدِيثَ
راہویہ
۱۶۱ھ تا ۲۳۸ھ
والوں میں سے ایک ہے.امام بخاری علیہ الرحمۃ مَتُرُوفُ الْحَدِيثِ واقدی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی روایت
۱۹۴ھ تا ۲۵۶ھ
لی جائے.امام یحیی بن معین لَيْسَ بِشَيْءٍ كَانَ يُقَلِبُ واقدی اہلِ علم کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتا.وہ حدیثوں کو بگاڑ بگاڑ کر بیان کیا کرتا تھا.امام شافی علیه الرحمة كُتُبُ الْوَاقْدِى كُلُّهَا واقدی کی سب کتابیں جھوٹ کا انبار ہیں.وہ
۱۸۵ھ تا ۲۳۳ھ
۱۵۰ تا ۲۰۴ھ کذبٌ كَانَ يَضَعُ اپنے پاس سے جھوٹی سند میں گھڑ لیا کرتا تھا.الاسانيد
امام ابو داؤد سجستاني لا أكُتُبُ حَدِيثَهُ إِنَّهُ كَانَ میرے نزدیک واقدی کی روایات مقبول نہیں، وہ
۲۰۲ھ تا ۲۷۵ھ يَفْتَعِلُ الْحَدِيثَ اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا.ا : میزان الاعتدال في نقد الرجال لعلامه ذهبي
Page 57
۴۲
امام نسائی علیہ الرحمۃ الْوَاقْدِى مِنَ الْكَذَّابِینَ واقدی ایسے جھوٹے لوگوں میں سے تھا جن کا
۲۱۵ھ تا ۳۰۳ھ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكِذَبِ جھوٹ ظاہر اور عیاں ہے اور اُسے سب جانتے
ہیں.محمد بن بشار بندار مَا رَأَيْتُ اَكْذَبُ مِنْهُ میں نے واقدی سے بڑھ کر کوئی جھوٹا نہیں دیکھا.۱۶۷ھ تا ۲۵۲ھ
امام نووی ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمُ واقدی سب محققین کے نزدیک بالا تفاق ضعیف
الروایت ہے.المتوفی ۶۷۴
علامہ ذہبی - اسْتَقَرَّ الْإِجْمَاعُ عَلَى وَهُن سب محققین نے واقدی کے مزور ہونے کے متعلق
المتوفى ۷۴۸ الْوَاقْدِى
اجماع کیا ہے.قاضی احمد بن محمد بن ضَعَفُوهُ فِي الْحَدِيثِ وَ محققین نے واقدی کو ضعیف قرار دیا ہے.اور اس
ابراہیم المعروف تَكَلَّمُوا فِيهِ
بابن خلکان.المتوفی ۶۸۱ ھ
پر بہت اعتراض کئے ہیں.علامہ زرقانی الْوَاقْدِى لَا يُحْتَجُ بِهِ إِذَا واقدی اگر کسی بات کے بیان کرنے میں اکیلا ہو تو
المتوفی ۱۱۲۲ھ اِنْفَرَدَ فَكَيْفَ إِذَا خَالَفَ محققین کے نزدیک اس کی روایت قابل حجت
نہیں ہے.پھر اس پر خود قیاس کرلو کہ ایسی بات
میں اس کی روایت کا کیا وزن ہو سکتا ہے جو وہ
دوسروں کے خلاف کہتا ہو.سے
یہ وہ شہادت ہے جو مسلمان محققین نے جن میں بہت سے خود واقدمی کے ہمعصر تھے پوری پوری تحقیق
کے بعد دی ہے.اب ہمارے یورپین مصنفین خود سوچ لیں کہ ان کا دل پسند مؤرخ کس شان کا انسان
ہے.ہم یہ نہیں کہتے کہ واقدی کی ہر روایت غلط ہے یقیناً اس کی روایتوں
کا بیشتر حصہ صحیح ہوگا.مگر جس شخص
تہذیب التہذیب لعلامہ ابن حجر
ے : شرح مواہب اللہ نبیہ لعلامہ زرقانی جلد ۱
: وفیات الاعیان القاضی ابن خلکان
Page 58
۴۳
کی صداقت وعدالت کا یہ حال ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے وہ اپنی کسی روایت میں بھی جس میں وہ اکیلا
راوی ہے یا جس میں وہ دوسرے راویوں کے خلاف بات کہتا ہے کسی عقلمند کے نزدیک قابل حجت نہیں سمجھا
جاسکتا.واللہ اعلم.بہر حال ہماری تحقیق میں محمد بن عمر واقدی با وجود ابتدائی مؤرخوں میں ہونے کے ہرگز قابل اعتبار
نہیں ہے.اور جہاں تک خالص سیرۃ کی کتب کا تعلق ہے صرف ابن ہشام اور ابن سعد اور ابن جریرطبری
ہی وہ تین ابتدائی مورخ ہیں جن کی کتب پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ وسوانح کی بنیاد سمجھی جانی
چاہئے.ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ان مؤرخین کی ہر روایت درست اور صحیح ہے ایسا دعوی مؤرخین تو در کنار
محد ثین کے متعلق بھی نہیں کیا جاسکتا.بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تین مؤرخ عموماً اپنی ذات میں قابلِ
اعتماد ہیں اور خواہ بے احتیاطی یا سند کی کمزوری کی وجہ سے ان کی بعض روایتیں بھی غلط اور نا درست ہوں مگر
بہر حال وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اصل حامل سمجھے جا سکتے ہیں؛ البتہ ان کی تائید میں یا
بعض ضمنی مسائل کے حل کے لئے مذکورہ بالا فہرست کی دوسری تاریخی کتب بھی کام دے سکتی ہیں.متأخرین کی کتب مذکورہ بالا کتب کے علاوہ باقی جتنی بھی کتا میں سیرۃ وتاریخ اسلام کے متعلق پائی
جاتی ہیں وہ خواہ کیسی ہی مفید اور جامع ہوں وہ سیرت میں اصل ماخذ نہیں سمجھی
جاسکتیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ لیا ہے مندرجہ بالا کتب سے لیا ہے.پس انہیں کسی تشریح کی تائید میں یا
سہولت کی غرض سے تو پیش کیا جاسکتا ہے، مگر سند کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا.مصنف کتاب ہذا نے بھی
اپنی اس تصنیف میں جہاں کہیں کسی بعد کی کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ صرف سہولت کے خیال سے دیا ہے تا کہ
متفرق حوالہ جات کی بجائے ایک حوالہ پر ہی اکتفا ہو سکے، لیکن ایسا حوالہ ہمیشہ اس تسلی کے بعد دیا گیا ہے
کہ اس کا اصل ابتدائی کتب میں موجود ہے بایں ہمہ متاخرین کی کتب بھی بڑی قدر و قیمت کی چیز ہیں،
کیونکہ اُن میں نہایت محنت و جانفشانی سے اصل کتب تاریخ و حدیث کی انتہائی ورق گردانی کے بعد ایک
قیمتی ذخیرہ جمع کر دیا گیا ہے اور بعض صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ ایک اصل کتاب تو اب نا پید ہے، لیکن کسی
بعد کے مؤرخ کی کتاب میں اس کی کسی روایت کے آجانے سے اس کا یہ حصہ محفوظ رہ گیا ہے اسی طرح
ایک محدود دائرہ کے اندر بعض متأخرین کی کتب بھی اصل ماخذ کا کام دے جاتی ہیں بشرطیکہ وہ خود معتبر اور
مستند ہوں.بہر حال متأخرین کی کتب سیرۃ و تاریخ میں سے مندرجہ ذیل کتب قابل ذکر ہیں :
Page 59
۴۴
1- الروض الانف مصنفہ عبد الرحمن بن عبد اللہ مہیلی یہ کتاب دو جلدوں میں ہے اور سیرۃ ابنِ
۵۰۸ھ تا ۵۸۱ھ ہشام کی شرح کے طور پر لکھی گئی ہے
نہایت معتبر اور مستند کتاب ہے.۲- تاریخ الکامل مصنفہ حافظ ابن اثیر الجزری یہ کتاب بارہ ضخیم جلدوں میں ہے اور
۵۵۵ھ تا ۱۳۰ھ زیادہ تر طبری سے ماخوذ ہے اور عمدہ
صورت میں مرتب شدہ ہے.اصل سیرة
کا حصہ صرف دوجلد میں آجاتا ہے.تاريخ الخميس في مصنفہ حسین بن محمد بن حسن دیار یہ کتاب دو جلدوں میں ہے اور بہت سی
احوال أنفس النفيس بکری المتوفی ۹۶۶ھ کتب کے معلومات کا مجموعہ ہے جو دلکش
صورت میں مرتب کیا گیا ہے.الله نیه
-۴- شرح مواہب مصنفہ علامہ محمد بن عبد الباقی بن یہ کتاب آٹھ ضخیم جلدوں میں ہے جو
یوسف الزرقانی سب کی سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
المتوفی ۱۱۲۲ھ کی سیرۃ سے متعلق ہیں.نہایت جامع
اور مستند کتاب ہے اور انتہائی تحقیق سے
لکھی گئی ہے.اس کتاب میں سیرۃ کی
روایتوں کے علاوہ احادیث کے حوالے
بھی کثرت کے ساتھ درج ہیں.خاکسار کی
رائے میں اس کتاب سے بڑھ کر کوئی جامع
اور محققانہ مجموعہ سیرۃ میں نہیں پایا جاتا.۵- انسان العيون في سيرة مصنفہ علی بن برہان الدین یہ کتاب جو تین جلدوں میں ہے اور
محکمی ۹۷۵ تا ۱۰۴۴ھ عرف عام میں سیرۃ حلبیہ کے نام سے
الامین المامون الحلمی
مشہور ہے نہایت جامع کتاب ہے مگر
افسوس کہ ترتیب چنداں دلکش نہیں ہے.
Page 60
۴۵
مشتمل
معجم البلدان مصنفہ ابو عبد اللہ یا قوت بن عبداللہ یہ کتاب دس جلدوں میں ہے اور جغرافیہ
کے نہایت مفصل معلومات پر
الحموی
المتوفی ۵۶۲۳
ہے.ان کے علاوہ سیرۃ کازرونی ۶۹۴ ھ ، سیرۃ مغلطائی ۷۶۲ ھ ، سیرۃ دمیاطی ۷۰۵ ھ ، سیرۃ خلاطی
۷۰۸ ھ ، سیرۃ ابن ابی طی ۶۳۰ ھ ، شرف المصطفیٰ نیشا پوری ۴۰۶ ھ ، اکتفاء ۶۳۴ ھ ، عیون الاثر لا بن سید
الناس ۳۴ ۷ ھ ، نور النبر اس شرح عیون الاثر ۸۴۱ ھ ، کشف اللثام ۸۵۵ ھ ، مواہب اللد نیه ۹۲۳ ھ ، سیرة
ابن عبدالبر ۴۶۳ ھ ، شرف المصطفیٰ ابن جوزی ۵۹۷ ھ ، تاریخ ابوالفداء۷۳۲ ھ وغیرہ بہت سی اور کتابیں
ہیں مگر ان میں سے کئی نا پید ہیں اور جو موجود ہیں وہ عموماً اس حیثیت کی نہیں ہیں کہ مندرجہ بالا کتب کے
ہوتے ہوئے کسی سند یا تشریح میں پیش کی جاسکیں.خلاصہ بحث خلاصہ کلام یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ابتدائی تاریخ اسلام کے
لیے مندرجہ ذیل اصول ماخذ سمجھے جاتے ہیں :
-1
-۲
قرآن شریف
کتب تفسیر منقوله
کتب حدیث
لد
كتب سيرة و تاريخ و مغازی
ان کے باہمی مدارج اسی ترتیب سے واقع ہیں جس میں کہ انہیں اُوپر درج کیا گیا ہے یعنی سب سے
زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ یقینی ماخذ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے قرآن شریف ہے جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ نبوت کی زندگی میں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا اور ساتھ ساتھ
ا : مختلف علوم و فنون میں اسلامی تصنیفات اور ان کے مصنفین کے حالات معلوم کرنے کے لئے دو کتابیں بہت مفید اور
قابل قدر ہیں.اعنی کتاب الفہرست مصنفہ ابن ندیم اور کتاب کشف الظنون عن اسامی الكتب والفنون مصنفہ علامہ ملا
کاتب چلپی.ان کتب سے اکثر اسلامی تصنیفات کا خواہ وہ کسی فن میں ہوں اور خواہ وہ اب تک محفوظ ہوں یا نا پید ہو چکی
ہوں اور ان کے مصنفین کے حالات کا پتہ چل سکتا ہے.اسی قسم کی ایک مستند کتاب و فیات الاعیان مصنفہ قاضی احمد بن
محمد بن ابراہیم ابن خلکان ہے جس میں جملہ مشاہیر اسلام کے مختصر حالات ترتیب وار درج کئے گئے ہیں.
Page 61
۴۶
ضبوط تحریر میں آتا گیا.یہ وہ کلید عمومی (ماسٹر کی) ہے جس سے سیرۃ رسُول اور تاریخ اسلام کی ہرا لجھن یقینی
صحت کے ساتھ کھولی جاسکتی ہے.دوسرے درجہ پر حدیث ہے جس کے سلسلہ روایت میں محدثین نے اپنی
طرف سے بڑی احتیاط کے ساتھ کام لیا ہے، مگر پھر بھی بہر حال وہ قرآن شریف کی قطعیت کو نہیں پہنچتی اور
بعض کمز ور روایتیں اس مجموعہ میں راہ پاگئی ہیں.تیسرے درجہ پر وہ تفسیری روایات ہیں جو قرآن شریف
کی تشریح و توضیح میں وارد ہوئی ہیں، مگر ان میں کمزور روایتوں کا حصہ بھی شامل ہو گیا ہے.چوتھے درجہ پر
سیرۃ و تاریخ کی ابتدائی کتا بیں ہیں جو تاریخی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ کی اصل بنیاد ہیں
مگر بدقسمتی سے یہی وہ ذخیرہ ہے جس میں کمزور اور ضعیف روایتوں نے زیادہ دخل پایا ہے، اس لیے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگار کا یہ پہلا فرض ہے کہ سیرۃ و تاریخ کی روایتیوں کی جرح و تعدیل
کے لیے قرآن شریف و حدیث کی شمع کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھے ورنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت و سوانح کا صحیح مرقع کبھی بھی تیار نہیں ہو سکے گا.اس اصولی بنیاد کے قائم کرنے کے بعد ہم اپنے اصل
موضوع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.وما توفيقنا الا بالله و نرجو منه خيرًا
Master Key :
Page 62
۴۷
عرب کا ملک اور اس کے باشندے
محل وقوع اور حد ودار بعہ یر اعظم ایشیا کے نقشہ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس
کے جنوب مغرب میں ایک جزیرہ نما واقع ہے جو وسعت رقبہ کے لحاظ
سے دُنیا کے تمام جزیرہ نماؤں میں سب سے بڑا ہے.یہ عرب کا ملک ہے، جہاں اسلام پیدا ہوا اور جہاں
اس نے اپنی طفولیت کے ایام گزارے.عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق اختلاف ہے.بعض کے نزدیک اس
کا نام عرب اس لئے پڑا ہے کہ عربی زبان اصول فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک ممتاز حیثیت رکھتی
ہے.حتی کہ بعض محققین عربی کو اُم الالسنہ یعنی تمام زبانوں کی ماں قرار دیتے ہیں.یا اور چونکہ لفظ عرب
کے روٹ میں فصاحت و بلاغت کے معنے پائے جاتے ہیں.اس لئے اس زبان کے بولنے والی قوم اور
ملک کا نام عرب مشہور ہو گیا ہے.ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ غیر آباد اور جنگلی حصہ کی زیادتی کی وجہ
سے اس کا یہ نام پڑا ہے.کیونکہ عرب کے معنے ایک غیر ذی زرع علاقہ کے بھی ہیں.جائے وقوع کے لحاظ سے عرب کا ملک قریباً نصف منطقہ حارہ میں واقع ہے اور نصف منطقہ معتدلہ
میں.گو یا خط سرطان اس کے وسط سے گذرتا ہے.عرب کی جنوبی اور شمالی حد و دعلی الترتیب ۱۳ عرض بلد
شمالی اور ۳۳ عرض بلد شمالی ہیں اور غربی اور شرقی حدود علی الترتیب ۳۳ اور ۶۰ طول بلد شرقی ہیں.حد و دار بعہ عرب کی یہ ہیں.مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عثمان.مغرب میں بحر احمر ہے.جنوب میں
بحر ہند ہے اور شمال میں شام اور عراق ہیں.شکل اور رقبہ
عرب کی شکل ایک بے قاعدہ سے مستطیل کی ہے جس کے تین طرف پانی ہے اور ایک
طرف خشکی.ساحل کی لمبائی ملک کی وسعت کے لحاظ سے بہت کم ہے جس کا لازمی نتیجہ
عمدہ بندرگاہوں کی کمی ہے.عرب کا رقبہ تقریب بارہ لاکھ مربع میل ہے اور طول اوسطاً سولہ سومیل ہے اور عرض اوسطاً سات سو میل
لے: دیکھو من الرحمن مصنفہ مقدس بانی سلسلہ احمدیہ قادیان.
Page 63
۴۸
ہے.گویا وسعت کے لحاظ سے عرب دُنیا کے بڑے ملکوں میں سے ہے، لیکن آبادی پر نظر ڈالیں تو بعض
چھوٹے سے چھوٹے ملک بھی اس سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں ؛ چنانچہ موجودہ زمانہ میں بھی عرب کی
مجموعی آبادی استی لاکھ سے زیادہ نہیں ہے.اس کی وجہ آگے ظاہر ہو جائے گی.سطح زمین سطح زمین اور نوعیت اراضی کے لحاظ سے ماہر ان جغرافیہ عرب
کو تین قسموں میں تقسیم کرتے
ہیں.اوّل.ساحلی علاقہ جو ہموار زمین پر مشتمل ہے اور باقی علاقوں کی نسبت معتدل
ہے.دوسرے پہاڑی علاقہ جس کے درمیان کی وادیاں گویا ملک کی جان ہیں.اور تیسرے صحرائی علاقہ
جو بوجہ ریگستان ہونے کے عموماً بنجر اور غیر آباد ہے.عرب کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ شمالاً جنوباً پہاڑوں کا ایک وسیع سلسلہ چلا گیا ہے جسے
جبل السراة کہتے ہیں.اس پہاڑی سلسلہ کی بعض چوٹیاں آٹھ ہزار بلکہ دس ہزار فٹ کی بلندی تک پہنچتی
ہے مگر اوسطاً بلندی بہت کم ہے.اس سلسلہ کے قریباً وسط سے ایک اور پہاڑی سلسلہ جو دراصل کئی پہاڑی
سلسلوں سے مرکب ہے اور شمالاً جنوباً بھی دُور تک پھیلا ہوا ہے، عرب کو دوٹکڑوں میں کا تھا ہوا ملک کے
مشرقی ساحل کی طرف نکل گیا ہے.اس وسیع علاقہ کو جو عرب کے وسط میں واقع ہے اور سطح سمندر سے
خاصا اونچا ہے سطح مرتفع نجد کہتے ہیں.اس کی اوسط بلندی چار ہزارفٹ سمجھی جاسکتی ہے.سطح مرتفع نجد کے
شمال اور جنوب اور کچھ مشرق میں نہایت وسیع صحرا واقع ہیں.عرب کا شمالی صحرا بالآ خر شمال میں صحرائے
شام سے جاملتا ہے اور جنوبی صحرا جو وسعت میں بہت بڑا ہے اور خالص ریگستان ہے الربع الخالی کے نام
سے مشہور ہے.عرب کے جنوب اور جنوب مشرق میں بھی خاصے اونچے پہاڑی سلسلے ہیں چنانچہ عمان کی
بعض چوٹیاں دس ہزار فٹ کی بلندی تک پہنچتی ہیں.عرب میں قابل ذکر دریا کوئی بھی نہیں ہاں وادیاں اور برساتی نالے ہیں جو بارش کے وقت بہہ نکلتے
ہیں اور بعض اوقات سیلاب کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، مگر عام طور پر پانی کی اس قدر قلت ہے کہ بعض
جگہ سینکڑوں میل تک پانی نہیں ملتا.کہیں کہیں چشمے ہیں اور انہی پر تمام آبادی کی سیرابی کا دارو مدار
ہے.ایسے چشمے جن کے ارد گرد د درخت اور باغات لگائے جاتے ہیں اور ان کے چاروں طرف میل ہا
میل تک بنجر صحرا ہوتا ہے نخلستان کہلاتے ہیں جو عرب میں ایک خاص نعمت سمجھے جاتے ہیں.عرب میں یمن
کا علاقہ سب سے زیادہ زرخیز اور شاداب ہے اور دوسرے علاقہ جات کی نسبت اس میں نالوں اور
چشموں کی بھی کثرت ہے.اسی طرح مکہ سے جنوب مشرق کی طرف ہیں میل کے فاصلہ پر طائف کا علاقہ
Page 64
۴۹
آب و ہوا
بھی ایک زرخیز اور خوشگوار علاقہ ہے جس میں اعلیٰ درجہ کے پھل پیدا ہوتے ہیں.ماہرین جغرافیہ جانتے ہیں کہ عرب کو بیرونی ہوائیں دو ہی طرف سے پہنچ سکتی ہیں.یعنی
شمال اور مشرق اور جنوب مغرب سے.مگر عرب کی ان دونوں طرفوں میں گویا خشکی ہی خشکی
ہے، اس لئے یہ ہوا ئیں بھی لازماً خشک ہوتی ہیں.یہی وجہ ہے کہ ملک میں عموماً بارش کی بہت قلت ہے.ہاں پہاڑی علاقے کچھ نہ کچھ پانی ان ہواؤں سے بھی نچوڑ لیتے ہیں.اور اس طرح ان علاقوں میں کچھ
بارش ہو جاتی ہے.خط سرطان کا ملک کے وسط سے گزرنا بھی اس کی صحرائی حالت اور کمی بارش کی وجہ بتلا
رہا ہے کیونکہ جیسا کہ جغرافیہ دانوں سے مخفی نہیں ایسا علاقہ دائمی ہواؤں کے لحاظ سے سکون کا منطقہ ہوتا
ہے.پس عام طور پر یہی کہا جائے گا کہ عرب ایک بہت خشک ملک ہے اور چونکہ کیا بوجہ اپنے محل وقوع کے
اور کیا بلحاظ نوعیت اراضی کے عرب عموماً ایک بہت گرم ملک ہے، اس لئے اس کی آب و ہوا بحیثیت مجموعی
گرم اور خشک کہلائے گی.عرب میں رات اور دن کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہوتا ہے جس کا باعث ریت کی کثرت ہے
جو دن کے وقت خوب تپتی ہے اور رات کو بہت جلد اپنی گرمی چھوڑ کر خوب ٹھنڈی ہو جاتی ہے.شبنم کی
کثرت بھی اسی وجہ سے ہے.عرب میں بعض اوقات ایک قسم کی گرم ہوا چلتی ہے جسے سموم کہتے ہیں.جب یہ ہوا چلتی ہے تو بالکل اندھیرا کر دیتی ہے اور اس میں اس قدر ریت اڑتی ہے کہ بعض اوقات اس کی
وجہ سے جان اور مال کا بڑا نقصان ہوتا ہے.موسم سرما میں ملک کے بعض حصوں میں کافی سردی پڑتی ہے؟
چنانچہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ جس موسم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق پیش آیا اس
میں مدینہ میں سردی کی اس قدر شدت تھی کہ لوگ سردی سے ٹھٹھرے جاتے تھے اور رات کو بستر سے اُٹھنا
غیر معمولی ہمت چاہتا تھا.مگر یہی علاقہ گرمیوں میں بھٹی کی طرح پیتا تھا.نباتاتی پیداوار کے لحاظ سے عرب کا ملک ایک نہایت ہی غریب ملک ہے.بعض جگہ سینکڑوں
میل تک سبزی کا نشان تک نہیں ملتا اور ملک کا بیشتر حصہ خشک پہاڑیوں اور بنجر صحراؤں سے بھرا
ہوا ہے.سب سے بڑی پیداوار کھجور ہے جو قریباً سارے آبا د ملک میں ہوتی ہے اور اس کی کئی قسمیں ہیں.عربوں کی اصل اور بڑی خوراک جس پر ان کا گزارہ ہے یہی ہے اور اس سے وہ کئی قسم کی اشیاء تیار کرتے
ہیں.عرب کے بعض حصوں میں دوسرے پھل بھی ہوتے ہیں اور جہاں پانی میسر ہے لوگوں نے اپنے باغ
لگارکھے ہیں.حجاز میں طائف اپنے باغات کے لئے خاص شہرت رکھتا تھا اور اب بھی رکھتا ہے.پیداوار
Page 65
وہ علاقے جہاں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے مثلاً بعض ساحلی علاقے اور پہاڑوں کی وادیاں وغیرہ.وہاں
بعض قبائل کھیتی باڑی کر کے اپنے لیے کچھ غلہ پیدا کر لیتے ہیں ؛ چنانچہ کو اور جوار کہیں کہیں بوئے جاتے
ہیں.کچھ گندم بھی ہو جاتی ہے.لوبیا اور دالیں اکثر جگہ ہوتی ہیں.بعض ترکاریاں بھی پیدا کی جاتی ہیں اور
قہوہ اور گرم مصالحہ جات بھی ہوتے ہیں.بارانی علاقوں میں گھاس وغیرہ اچھا اُگ آتا ہے.یہ علاقے
جانوروں کے واسطے چراگاہ کا کام دیتے ہیں.تمام قبائل کی اپنی اپنی چرا گا ہیں الگ الگ مقرر ہیں.سطح
مرتفع نجد خصوصاً چرا گا ہوں کا مرکز ہے.حیوانی پیداوار کے ضمن میں تین جانور خصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں.یعنی اونٹ ، گھوڑا اور گدھا.اونٹ تو گویا عرب کی ضروریات زندگی کا حصہ ہے.اس کے بغیر عرب جیسے ملک میں سفر کرنا قریباً محال
ہے.ضرورت کے وقت اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں.عرب کا گھوڑا بعض خوبیوں کی وجہ سے دُنیا میں
ممتاز حیثیت رکھتا ہے.عرب لوگ اسے بہت عزیز رکھتے ہیں اور عام طور پر اس کی نسل باہر جانے نہیں
دیتے.نجدی گھوڑا عرب میں خاص قدر و وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے.گدھا بھی عام ہے اور سواری
کے کام میں استعمال ہوتا ہے.زمانہ جاہلیت میں عرب اس کا گوشت بھی کھاتے تھے.عرب میں بھیڑ
بکریاں بھی بہت ہوتی ہیں اور امراء ان کے گلے کے گلے رکھتے ہیں.گائے بیل بھی ہوتے ہیں، مگر کم.بھینس عرب میں نہیں ہوتی.جنگلی جانوروں میں شیر، چیتا بعض علاقوں میں ملتا ہے.بھیڑ یئے ،لگڑ بگڑ ، بندر اور گیدڑ وغیرہ کافی
ہوتے ہیں.ہرن بھی ملتا ہے اور جنگلی بکری بھی پہاڑوں میں پائی جاتی ہے.گورخر ( جنگلی گدھا) بھی ہوتا
ہے جس کا عرب لوگ شوق سے شکار کھیلتے ہیں.پرندوں میں عام پرندوں کے ذکر کو ترک کرتے ہوئے صرف شتر مرغ قابل ذکر ہے.یہ ایک بہت بڑا
جانور ہوتا ہے جس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں اور ایسا تیزی سے بھاگتا ہے کہ گھوڑے کو بھی پاس پھٹکنے نہیں دیتا.رینگنے والے جانوروں میں سے صرف گرگٹ کی قسم کے جانوروں کی کثرت ہے باقی کم ہیں.گو
سانپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں.ٹڈی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے کثرت کے ساتھ ہوتی ہے.اور باغات اور فصلوں وغیرہ کا بڑا
نقصان کرتی ہے.ساحل کے قریب مچھلی بھی ملتی ہے اور لوگ اسے پکڑتے ہیں.معدنی پیداوار عرب کی بہت کم ہے.قیمتی اور کار آمد دھاتیں تو گویا بالکل ہی نہیں ہیں کچھ سیسہ اور
Page 66
۵۱
تانبا ملتا ہے اور کچھ کچھ چاندی اور لو ہا.کوئلہ.گندھک اور نمک بھی پائے جاتے ہیں.سونا بھی کہیں کہیں
موجود ہے.اور ایک انگریز مسٹر برٹن نے مدین میں اس کی تلاش بھی کی تھی ، مگر کامیابی نہیں ہوئی.بحرین
میں سمندر کے کناروں سے موتی بھی نکالے جاتے ہیں اور ان کی خاصی تجارت ہے.اب تو پٹرول کے
بڑے بڑے ذخائر عرب میں دریافت ہو چکے ہیں.ملکی تقسیم ملکی تقسیم کے لحاظ سے عرب
کئی حصوں میں منقسم ہے جن میں بڑے بڑے حصے یہ ہیں :
۱.مغرب میں حجاز ہے جو بحر احمر کے ساتھ ساتھ یمن سے لے کر شام تک پھیلے ہوئے ساحلی
علاقے کا نام ہے.اس میں مکہ اور طائف اور مدینہ اور جدہ وغیرہ بڑے بڑے شہر آباد ہیں.ظہو ر اسلام
کے وقت عرب مستعربہ میں سے قبائل بنو کنانہ، قبائل ھذیل اور قبائل ہوازن اور بنو قحطان میں سے بعض
قبائل ازد وغیرہ اس علاقہ میں آباد تھے.-۲
حجاز کے جنوب میں اور بعض کے نزدیک اُس کے اندر شامل تہامہ بھی ایک مشہور علاقہ ہے جو بحر احمر
کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہے.عرب کے جنوب مغرب میں یمن ہے جو ایک بہت مشہور اور نہایت شاداب علاقہ ہے.قدیم زمانہ
میں یہ ایک اچھی طاقتور اور متمدن سلطنت کا مرکز تھا اور ظہور اسلام سے قبل حبشہ کے اور ظہو را سلام کے
وقت فارس کے ماتحت تھا.اس کا بڑا شہر صنعاء کسی زمانے میں بہت مشہور اور سلطنت یمن کا پایہ تخت تھا.سبا کی قوم جس کا قرآن شریف میں ذکر آتا ہے ایک زمانہ میں اس جگہ آباد تھی.بنو قحطان کا مولد و مسکن بھی
یمن تھا.اور یہیں سے اکثر قبائل بنو قحطان نے عرب کے شمال کی طرف رحلت کی تھی ، چنانچہ مدینہ کے اوس
اور خزرج بھی جنہوں نے اسلام میں انصار کا لقب پایا ، یہیں سے گئے تھے.یمن کے ساتھ ہی ملا ہو ایک اور علاقہ نجران ہے جو یمن کے شمال مشرق میں واقع ہے.ظہور اسلام
کے وقت یہ علاقہ عرب کے عیسائیوں کا بڑا مرکز تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے لئے جس کا
ذکر قرآن شریف میں بھی آتا ہے انہی لوگوں کو بلا یا تھا.عرب کے جنوب میں یمن کے مشرق کی طرف حضر موت ہے اور حضر موت کے مشرق کی طرف مہرہ
ہے.یہ ہر دو مشہور علاقے ہیں.-۴- عرب کے جنوب مشرق میں عثمان ہے جس کا دارالخلافہ مسقط ایک مشہور شہر ہے.- مشرق میں خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ الحساء کا علاقہ ہے جس کے قریب میں بحرین کے جزائر ہیں
Page 67
۵۲
اور اسی وجہ سے بعض اوقات الحساء کو بحرین بھی کہہ لیتے ہیں.بحرین کے ساحل سے موتی نکالے جاتے ہیں.- وسط عرب میں نجد ہے جو ایک نہایت وسیع اور مشہور علاقہ ہے اور کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جن میں
سے بعض عرب کے شاداب حصوں میں شمار ہوتے ہیں منقسم ہے.قبائل غطفان اور سلیم وغیرہ اس جگہ آباد
تھے.یمامہ جو نجد کے جنوب مشرق میں ہے.بنو حنیفہ یعنی مسیلمہ کذاب کے قبیلے کا مسکن تھا.یمامہ اور حضر موت کے درمیان الاحقاف ایک معروف علاقہ ہے.قوم عاد کا جن کی طرف حضرت
ہو مبعوث ہوئے تھے ، یہی مسکن تھا.مگر آجکل یہ بالکل ویران و غیر آباد ہے.- نجد کے شمال مشرق میں حجاز کے ساتھ ملا ہوا خیبر بھی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو قدیم زمانہ میں یہود کا
ایک بڑا مرکز تھا اور قلعوں کے ساتھ مستحکم کیا گیا تھا.خیبر کے شمال مشرق میں تیما بھی یہود کا ایک مرکز تھا.تیما کے قریب ہی حجر کی بستی ہے جس میں شمود کی قوم آباد تھی جس کی طرف حضرت صالح" مبعوث ہوئے
تھے.تحجر کے غربی جانب ساحلِ سمندر کی طرف مدین کا علاقہ ہوتا تھا جہاں حضرت موسیٰ اپنی بعثت سے
پہلے حضرت شعیب کے پاس آ کر ٹھہرے تھے.باشندے عرب ایک بہت
کم آباد ملک ہے.بارش کی کمی ، ریگستان کی زیادتی ، نباتاتی اور معدنی
پیداوار کی قلت وغیرہ کئی باتوں نے مل ملا کر اس کی آبادی کو بڑھنے نہیں دیا.پھر بھی آج
کل ستر اسی لاکھ کے قریب اس کی آبادی بتائی جاتی ہے جو ملک کے حالات کے ماتحت کم نہیں ہے.تقسیم اقوام کے لحاظ سے مؤرخین نے قبائل عرب کو دو اور ایک لحاظ سے تین بڑے حصوں میں
تقسیم کیا ہے.اول - عرب عاربہ
یعنی ملک کے قدیم اور اصلی باشندے جو آگے پھر دوحصوں میں تقسیم کئے گئے
ہیں:
(الف) عرب کے وہ قدیم ترین باشندے جو اسلام سے بہت عرصہ پہلے فنا ہو چکے تھے.بعد زمانہ کی وجہ
سے ہمیں اُن کے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہیں، مگر اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی قبائل تھے اور ملک کے مختلف
حصوں میں آباد تھے اور ان میں سے بعض قبائل کی اچھی اچھی زبر دست اور متمدن ریاستیں تھیں.عاد نمود،
طسم ، جدیں اور جرہم الاولیٰ وغیرہ انہی میں سے چند مشہور قبائل کے نام ہیں.عاد کا وطن احقاف میں تھا
اور ثمود حجاز کے شمال میں جوف میں آباد تھے.ان قدیم ترین قبائل کو ان کے فنا ہو جانے کی وجہ سے عرب
بائدہ بھی کہتے ہیں.
Page 68
۵۳
(ب) وہ قبائل جو بنو قحطان کہلاتے ہیں اور بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ حضرت ہود کی اولاد سے
تھے.بہر حال یہ عرب بائدہ کے بعد ملک میں پھیلے.ان کا اصل وطن یمن تھا جہاں سے یہ سارے عرب
میں پھیل گئے اور ان کی کئی شاخیں ہو گئیں.عرب کے شمال میں سلطنت فارس و روم کے ساتھ علی الترتیب ملی ہوئی حیرہ اور غستان دو مشہور
ریاستیں تھیں.ان کے فرماں روا بھی بنو قحطان سے تھے.ظہور اسلام کے وقت بنو قحطان بہت کھیل
-
چکے تھے اور ملک میں ان کا کافی زور تھا.اور ملک کا ایک بڑا حصہ اُن سے آباد تھا.مدینہ کے قبائل
اوس و خزرج بھی بنو قحطان میں سے تھے.بعض اوقات عرب عاربہ کی اصطلاح صرف بنو قحطان کے واسطے استعمال کی جاتی ہے جس کی وجہ یہ معلوم
ہوتی ہے کہ عرب کے قدیم اور اصلی باشندوں میں سے یہی وہ قوم تھی جو مستقل طور پر ملک میں قائم رہی.بنو قحطان کے مشہور قبائل کا شجرہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے.(دیکھئے اگلا صفحہ )
: زرقانی جلد ا صفحه ۹۲
Page 69
حضرت نوح علیہ السلام
سام
قحطان
جر ہم
مضاض
بنو عامله
کہلان
اشعر
ازو
همدان مذحج كندة
مراد
انمار
قضاعة
متابع
بنوشعبان
سکاسک سکون
بجیلہ
بنو الدار مناذرة
حرام
خوان
عبس
بنو سعد العشيره
(
ملوک حیره)
جديلة نبہان بولان سلامان ھنی سدوس
جعف
زبید
جمہینہ بہرا
نخی تنوخ بنو عذرة
خزاعه
غستان اوس خزرج
بارق عتیق غافق دوس بنوالجلندی (ملوک عمان)
بنو المصطلق
Page 70
وم - عرب مستعربه
یعنی باہر سے آئے ہوئے لوگ جو عرب میں آ کر آباد ہوئے.اُن میں زیادہ
تر حضرت
اسمعیل بن ابراہیم علیہما السلام کی اولاد تھی جو حجاز میں آکر آباد ہوئی.ان کو عدناتی بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت اسمعیل کی اولاد میں بڑا شخص جس سے یہ لوگ پھیلے عدنان تھا.بنو
عدنان بھی آہستہ آہستہ کئی شاخوں میں منقسم ہو گئے.اور ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئے.قریش جن
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بنو عدنان ہی کی ایک شاخ تھے.اور جیسا کہ آگے ظاہر ہو جائے
کا ظہو ر ا سلام کے وقت عرب مستعربہ میں سب سے زیادہ طاقتور اور صاحب اثر قریش ہی کا قبیلہ تھا.عرب مستعر بہ کے متعلق یہ بات یا درکھنی چاہیے کہ عدنان حضرت
اسمعیل سے کئی پشت بعد پیدا ہوئے
تھے.مگر چونکہ عدنان اور حضرت اسمعیل کی درمیانی کڑیوں کے متعلق روایات میں کچھ اختلاف ہے اس
وجہ سے بعض غیر مسلم مؤرخین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل اسمعیل میں ہونے کے متعلق اعتراض کا
موقع مل گیا ہے، حالانکہ جس صورت میں عرب کی متفقہ روایات کی رُو سے حضرت اسمعیل“ کا عرب میں
آکر آباد ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسری طرف عدنان کے متعلق عرب کی تمام روایات متفق ہیں کہ وہ
حضرت اسمعیل کی اولاد سے تھا تو درمیانی کڑیوں کے متعلق اختلاف اصل مسئلے پر ہر گز کوئی اثر نہیں ڈال
سکتا ہے
بہر حال مشہور عدنانی قبائل کا شجرہ درج ذیل ہے:
(دیکھئے اگلا صفحہ)
ل : زرقانی جلد اصفحه ۸۰
Page 71
حضرت ابراہیم خلیل اللہ
الفيل
عدنان
معد
نزار
آیاد
انمار
صفہ
محارب
قیس عیلان
الیاس
طابخه خندف
غطفان بابلہ ہوازن بنو کلاب مازن عقیل عدوان
محمد
بنو سعد بنو بحر بنو ثقیه
رعل ذکوان
عصر
زبیان
بنو ہلال
ربیعہ
لهازم سدوس
مدرکه
ضبة بنو مزینہ
هذيل
ثور کنانہ ہون
اسد
لحیان
I
و.دووان کاہل
رياح
قاره
وائل
عبد مناة عمرو (عمریون)
عامر (عامر یون)
احالیش ماکان مالک
بنوفراس
تغلب
بنو شیبان
قارضان
مرة
فزارة
بنو غقار بنوليت بنو الحارث بنو مدلج بنو ضم
فهر (
قریش)
Page 72
۵۷
ظہور اسلام سے پہلے عرب کا تہذیب و تمدن ظہور اسلام سے پہلے عرب کا ملک سوائے
چند ساحلی علاقوں کے بیرونی دنیا سے ایک
بالکل منقطع حالت میں تھا.حتی کہ نہ اُس پر
کبھی کسی بیرونی قوم یا سلطنت کا اثر ہوا اور نہ عرب لوگ خود کبھی
مستقل طور پر اپنے وطن سے باہر نکلے.خود ملک کے اندر بھی اسلام سے پہلے کبھی کوئی متمدن مرکزی
سلطنت قائم نہیں ہوئی.بے شک بعض اوقات بعض علاقہ جات میں بعض ریاستیں قائم ہوئیں مگر اُن کا اثر
صرف مقامی تھا اور تمام ملک کبھی بھی کسی ایک تاجدار کے سامنے نہیں جھکا، بلکہ عموماًہر قبیلہ آزاد تھا اور اپنا
الگ الگ سردار رکھتا تھا.مگر عرب میں سرداری کسی کو با قاعدہ ورثہ میں نہ ملتی تھی اور نہ ہی یہ سرداری کوئی
با قاعدہ حکومت کے رنگ میں ہوتی تھی، بلکہ عموماً کسی قبیلہ میں جو شخص سب سے زیادہ قابل ہوتا تھا، اُس
کی مرضی پر لوگ چلتے تھے اور وہ قوم کا سردار سمجھا جاتا تھا.طرز زندگی کے لحاظ سے عربوں کی خوراک و لباس اور عام کو دوباش نہایت سادہ اور ابتدائی تھی.عام خوراک عربوں کی اونٹوں اور بکریوں کا دُودھ اور کھجور تھی.جو کے ستو بھی عموماً استعمال ہوتے تھے.ذی ثروت لوگ گوشت بھی کھاتے تھے اور اونٹ یا بکری کے بھنے ہوئے گوشت کو بہت پسند کیا جاتا تھا.شوربے میں روٹی کو بھگو کر کھانا ایک اعلی قسم کی غذا سمجھی جاتی تھی جسے عرب لوگ ثرید کہتے تھے.لباس میں
بھی یہی سادگی اور غربت کا عالم تھا.عام لوگوں کے پاس ایک چادر سے زائد کپڑا نہ ہوتا تھا جو وہ تہہ بند
کے طور پر باندھے پھرتے تھے.قمیص صرف خاص خاص لوگ استعمال کرتے تھے اور جُبہ تو گویا ایک بڑی
نعمت تھی.گھروں میں عموماً فرش یا چار پائی نہیں ہوتی تھے.لوگ عموماً کھجور کی چٹائیوں پر سوتے تھے البتہ
ذی ثروت لوگوں میں لکڑی کے تخت استعمال ہوتے تھے.اوڑھنے کو عموماً اُونٹ کی اون کے بنے ہوئے
بھڑے سے کمبل ہوتے تھے.باقاعدہ مکان کم تھے عموماً خیمے یا پھوس کے چھپر یا کچے مکان استعمال ہوتے
تھے ؛ البتہ بعض خاص خاص عمارتیں پتھروں کی بھی بنائی جاتی تھیں.تقسیم آبادی کے لحاظ سے عرب دو حصوں میں منقسم تھے.الحضر اور البد و یعنی شہروں میں رہنے
والے اور جنگل میں رہنے والے.شہروں میں رہنے والے چونکہ ایک جگہ جم کر سکونت اختیار کرتے تھے.اس لیے اُن کا ایک خاص تمدن تھا اور اُن میں ایک مدنیت کا رنگ تھا مگر بدوی لوگوں کی زندگی جنگلی اور
خانہ بدوشوں کی سی زندگی تھی.وہ خیموں اور عارضی گھروں میں رہتے تھے اور اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو لے
کر ایک وسیع علاقہ میں ادھر اُدھر آزادانہ پھرتے رہتے تھے.جہاں پانی اور سبزی پاتے وہیں ڈیرہ لگا
Page 73
۵۸
دیتے.پھر کسی اور طرف نکل جاتے.اسی طرح اُن کی ساری عمر بسر ہو جاتی تھی.اس طرز زندگی کے
نقشے قدیم شاعروں نے اپنے کلام میں نہایت خوبی کے ساتھ کھینچے ہیں.ان لوگوں کی زبان شہری لوگوں
کی نسبت زیادہ صاف اور خالص تھی اور ان میں اصل عربی فطرت اور عربی عادات کی تصویر زیادہ واضح
طور پر نظر آتی ہے.ان کا پیشہ زیادہ تر ایک چرواہے کا سمجھنا چاہیے.عربوں میں لین دین عموماً جنس کا جنس سے ہوتا تھا، لیکن سونے اور چاندی کے بھرے سے سکے بھی
چلتے تھے.چنانچہ چاندی کے دو سکے رائج تھے، درہم اور اوقیہ.ایک اوقیہ کی قیمت چالیس درہم کے برابر
سمجھی جاتی تھی.سونے کا مروّج سکہ دینار تھا.ترازو سے تولنے کا رواج کم تھا.عموماً ماپ کا دستور تھا؛
چنانچہ مڈ اور صاع عرب کے دو مشہور پیمانے تھے.ناپنے کا آلہ صرف ذراع یعنی ہاتھ تھا جسے گویا ڈیڑھ
فٹ کے برابر سمجھنا چاہئے.ختنہ کی رسم عربوں میں عام تھی.حتی کہ بعض اوقات عورتیں بھی ختنہ کرواتی تھیں.مُردوں کو غسل
دینے اور کفن میں لپیٹ کر دفن کرنے کا رواج تھا.عرب لوگ داڑھی رکھتے اور عموماً مونچھیں کتر واتے
تھے.سُود لینے دینے کا رواج بھی کم و بیش پایا جاتا تھا.عربوں کی تجارت عربوں کے قومی پیشے صرف تین تھے.اوّل زراعت جو ملک کے ایک نہایت
قلیل حصہ تک محدود تھی.دوسرے مویشیوں کا پالنا جسے انگریزی میں پاسچرنگ
کہتے ہیں.یہ بھی ملک کے صرف خاص خاص حصوں میں ہی ممکن تھا.تیسرے تجارت جسے گویا ملک کا
سب سے بڑا پیشہ سمجھنا چاہئے عرب کے لوگ ہمیشہ سے تجارت پیشہ رہے ہیں.خصوصاً وہ قبائل جو ساحل
سمندر کے پاس یا متمدن ملکوں کے قرب میں آباد تھے قدیم سے تجارت میں مصروف چلے آئے ہیں.ابتدائی زمانہ میں تو مشرق و مغرب کے درمیان تجارتی مال لانے اور لے جانے کا بڑا ذریعہ عرب لوگ ہی
تھے ، چنانچہ ایک طرف شام و مصر اور دوسری طرف سواحل بحر ہند کے درمیان ان کے تجارتی قافلے برابر
آتے جاتے تھے جو گو یا ہندوستان اور شام ومصر کے درمیان ایک تجارتی کڑی کا کام دیتے تھے.مگر سمندر
کا راستہ کھل جانے سے عربوں کی اس تجارت کو سخت نقصان پہنچا اور اس قدیم راستہ پر جو شام سے حجاز اور
پھر یمن اور پھر حضر موت کے اندر سے ہوتا ہوا عرب کے مشرقی ساحل کی طرف جاتا تھا تجارتی قافلوں کی
آمد و رفت عملاً بالکل رُک گئی اور صرف ملک کے اندر کی معمولی تجارت باقی رہ گئی.یہ اندرونی تجارت
حجاز ، یمن ، بحرین اور نجد وغیرہ کے اندر محدود تھی مگر آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قریباً ایک سو
Page 74
۵۹
سال پہلے شام کے ساتھ حجاز و یمن کی تجارت کا سلسلہ پھر شروع ہوا.گو اس پہلے پہیا نہ پر تو نہ تھا اور نہ ہوسکتا
تھا لیکن پھر بھی ملک میں اس سے کچھ جان آگئی تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریش مکہ
کے تجارتی قافلے با قاعدہ شام اور یمن کی طرف آتے جاتے تھے اور بعض اوقات عرب کے دوسرے
حصوں کی طرف بھی جاتے تھے مگر اس زمانہ میں قریش مکہ کی بڑی تجارت شام سے تھی.مکہ سے شام کی
طرف جانے کا زیادہ مستعمل راستہ بحر احمر کے ساتھ ساتھ شمال کو جا تا تھا.میثرب کا شہر جس نے بعد میں
مدینہ کا نام پایا اسی راستہ کے قرب میں واقع تھا.شامی راستہ پر وہ مقام جہاں سے مدینہ کا راستہ مشرق کی
طرف الگ ہو جاتا تھا بدر ہے جہاں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان سب سے پہلی لڑائی ہوئی.بر آمد کا مال عموماً قیمتی دھاتوں ، موتیوں، جانوروں کی کھالوں ، گرم مصالحہ جات اور خوشبو دار چیزوں
پر مشتمل ہوتا تھا.اور جیسا کہ قیاس کیا جاتا ہے درآمد بالعموم غلہ.پار چات.سامانِ حرب.شراب اور
کھانے کی خشک چیزوں پر مشتمل تھی.عرب میں قاعدہ تھا کہ سال کے مختلف حصوں میں ملک کے مختلف مقاموں میں تجارتی میلے لگا کرتے
تھے جن میں دور دراز سے تاجر لوگ آ کر شامل ہوتے اور تجارت کرتے تھے.ان میلوں کے لیے قرب شام
میں دومتہ الجندل بحرین میں مشقر ، عمان میں دبا ، یمن میں صنعا اور حجاز میں عکاظ خاص شہرت رکھتے تھے.تعلیم اور قدیم شاعری تعلیم عرب میں تھی تو سہی مگر بہت ہی کم تھی.سوائے خاص خاص اشخاص
کے سارا ملک ان پڑھ تھا اور یہ چند خواندہ لوگ بھی زیادہ تر شہروں میں
آباد تھے، مگر باوجود اس جہالت کے عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا گھمنڈ تھاحتیٰ کہ عرب اپنے سوا
باقی تمام دنیا کو عجمی یعنی گنگ کہتے تھے اور اس میں شک نہیں کہ زبان کی فصاحت میں عرب کو واقعی حد درجہ
کمال حاصل تھا.زمانہ جاہلیت کے شعراء کا کلام آج تک محفوظ ہے اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ، جو
زور اور جوش و خروش ، جو آزادانہ زندگی کی جھلک اور طبعی بہاؤ کی لہریں نظر آتی ہیں وہ کسی اور قوم اور کسی
اور وقت کی شاعری میں کم ملیں گی.اور ان لوگوں میں یہ ایک خصوصیت تھی کہ اپنے دلی خیالات کو نہایت
بے تکلفی کے ساتھ بالکل تنگی زبان میں کہہ جاتے تھے کوئی تصنع نہیں کوئی بناوٹ نہیں طبیعت پر کوئی زور
نہیں.اسی لیے اُن کا کلام ان کے خیالات.جذبات اور عادات کی پوری پوری ترجمانی کرتا ہے.عرب قوم اپنی اس خوبی کو خود بھی خوب سمجھتی تھی ، چنانچہ ایک مؤرخ نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
عرب ایک دوسرے کو صرف تین موقعوں پر مبارکباد کہتے تھے.اول
کسی لڑکے کی ولادت پر.دوسرے کسی
Page 75
۶۰
شاعر کے سر نکالنے پر اور تیسرے عمدہ چھیرے کے پیدا ہونے پر یا اس مختصر فقرہ میں عربی زندگی کا پورا
نقشہ آ جاتا ہے.عرب میں شعراء گویا ملک کے لیڈر سمجھے جاتے تھے.اُن
کو یہ طاقت حاصل تھی کہ اپنے کلام کے زور
سے دو قبائل کے درمیان جنگ کرا دیں اور ملک میں آگ لگا دیں.عرب کے خاص خاص مقامات میں
شعراء جمع ہو کر طبع آزمائیاں کرتے تھے.عکاظ جو نخلہ اور طائف کے درمیان مکہ سے مشرق کی طرف
ایک شاداب جگہ ہے ایسے میلوں کے لئے زمانہ جاہلیت میں خاص شہرت رکھتا تھا.یہاں ہر سال ذی قعدہ
میں میلہ لگتا تھا اور دُور دراز سے لوگ جمع ہوتے تھے اور علاوہ دوسری باتوں کے مختلف قبائل عرب کے
درمیان فصاحت و بلاغت اور شاعری کے مقابلے بھی ہوا کرتے تھے.فتح مکہ کے بعد جب تمام اطراف عرب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف قبائل
کے وفد حاضر ہوئے تو اُن میں سے بنو تمیم نے جو معیار صداقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش
کیا اس سے ملک عرب میں شاعری کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے.انہوں نے بجائے اور دلیلوں میں پڑنے
کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے اور اپنے شاعر کا
مقابلہ کرا کے دیکھیں ؛ چنانچہ انہوں نے اپنا شاعر کھڑا کر دیا جس نے اپنے قبیلہ کی تعریف میں چندا شعار
کہے.پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے حسان بن ثابت انصاری کو کھڑے
ہونے کا ارشاد فرمایا جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تعریف میں چند زوردار
شعر کہے جن کی فصاحت کا لوبا بنو تمیم و ماننا پڑا اور اس کے بعد یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا.عادات اور قومی خصائل عرب کے گندے خصائل میں سے ان کی تین عادتیں خاص امتیاز رکھتی
تھیں.شراب خوری ، قمار بازی اور زنا.ملک میں ان کی اتنی کثرت تھی
کہ خدا کی پناہ اور اس پر تعجب یہ ہے کہ عموماً ان کو جائے فخر سمجھا جاتا تھا؛ چنانچہ زمانہ جاہلیت کے شاعر
بڑے مزے لے لے کر ان سیہ کاریوں کے متعلق اپنے کارنامے سُناتے ہیں بلکہ اس قسم کے ذکر کے
بغیر عربوں میں شعر کی کچھ حقیقت ہی نہ سمجھی جاتی تھی ، چنانچہ یہ ضروری خیال کیا جاتا تھا کہ قصیدہ کے
شروع میں خواہ وہ کسی غرض سے کہا گیا ہو شاعر چند کھلی کھلی باتوں میں اپنی اصل یا مفروضہ معشوقہ کا ذکر
کرے اور اس کے ساتھ اپنی چند مجلسوں کے کارنامے سُنائے.کعب بن زہیر ایک مشہور شاعر تھا وہ
ل : المزهر مصنفه امام سیوطی.: ابن هشام ذكر وفد بنو تميم -
Page 76
บ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہہ کر لایا جو آجکل
بانَتْ سُعاد کے نام سے مشہور ہے.اس کے شروع میں بھی شاعر اپنی محبوبہ ہی کی جدائی کا ڈ کھڑا روتا ہے.بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات خود مالک اپنی لونڈیوں سے بدکاری کرواتے اور اس کی آمد وصول
کرتے تھے.یہ بھی گویا ایک آمد کا ذریعہ تھا، مگر شرفاء کا دامن اس قسم کی انتہائی بے حیائی سے پاک تھا.جہالت اور بے جا جوش و خروش کا عرب میں یہ حال تھا کہ بات بات پر تلوار چل جاتی تھی.تاریخ
سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک ذراسی بات پر دو قبیلوں میں جنگ شروع ہوئی پھر آہستہ آہستہ بعض
دوسرے قبائل بھی شریک ہو گئے اور سالہا سال تک قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا.ذیل کا واقعہ ایام
عرب کی تاریخ کا ایک معمولی ورق ہے.پانچویں صدی عیسوی کے آخر میں کلیب بن ربیعہ ایک بڑا طاقتور اور صاحب اثر رئیس گذرا ہے یہ
قبیلہ بنو تغلب بن وائل کا سردار تھا جو عرب کے شمال مشرق میں رہتے تھے.کلیب کی بیوی حلیلہ بنت مرة
قبیلہ بنو بکر بن وائل سے تھی.اس حلیلہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام جساس تھا جو اپنی خالہ بسوس کے ساتھ رہا
کرتا تھا.اب اتفاق ایسا ہوا کہ بسوس کے پاس ایک شخص سعد نا می بطور مہمان آ کر ٹھہرا.سعد کی ایک اونٹنی
تھی جس کا نام سراب تھا.....جو بوجہ تعلقات رشتہ داری کے کلیب کی چراگاہ میں جستاس کی اونٹنیوں
کے ساتھ مل کر چرا کرتی تھی.ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ کلیب ایک درخت کے نیچے سے گذر رہا تھا کہ درخت کے اوپر سے اس کو
ایک پرندے کی آواز آئی.کلیب نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک پرندے نے اس درخت پر
ایک گھونسلا بنا کر اس میں انڈے دے رکھے تھے.کلیب نے اس پرندے کی طرف اپنے سردارانہ بددی
انداز میں دیکھا اور بولا ” کسی سے مت ڈر میں تیری حفاظت کروں گا.“ دوسرے دن جب کلیب وہاں
سے گذرا تو اس نے دیکھا کہ انڈے درخت سے نیچے گرے پڑے ہیں اور کسی جانور کے پاؤں سے مسلے
ہوئے ہیں اور پرندہ اوپر درد بھری آواز نکال رہا ہے.کلیب کو اپنی کل کی بات یاد آئی اور اس کی آنکھوں
میں خُون اُتر آیا.اس نے ادھر اُدھر نظر کی تو سعد کی اونٹنی چر رہی تھی.کلیب نے خیال کیا کہ ضرور انڈے
اسی اونٹنی نے توڑے ہوں گے غصہ سے مغلوب ہو کر وہ اپنے سالے جناس کے پاس آیا اور کہنے لگا."
دیکھو جناس ! اس وقت میرے دماغ میں ایک خیال ہے اگر مجھے اس کا یقین ہو تو میں کچھ کر گذروں.مگر
دیکھو آئندہ سعد کی یہ اونٹنی اس گلے کے ساتھ یہاں نہ چرا کرے.‘ جساس کی رگوں میں بھی عرب کا
Page 77
۶۲
بدوی خون تھا اس نے سامنے سے جواب دیا.”یہ ہمارے مہمان کی اونٹنی ہے جہاں میری اونٹنیاں چریں
گی وہیں یہ بھی چرے گی.کلیب نے کہا.”اچھا تو اگر مجھے یہ اونٹنی پھر یہاں نظر آئے گی تو میں اس کے
شیر دان میں تیر مار کر اسے ہلاک کر دوں گا.جساس بولا.اگر تو نے ایسا کیا تو مجھے بھی وائل کے جُجوں کی
قسم ہے کہ میں خود تیرا سینہ تیر سے چھید کر رکھ دوں گا.“ یہ کہہ کر جساس وہاں سے چلا گیا اور کلیب سخت
غضب کی حالت میں اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی حلیلہ سے کہنے لگا.” کیا تو کسی ایسے آدمی کو جانتی ہے جو
میرے مقابل پر اپنے پڑوسی کی حفاظت کی جرات کرے گا.اس نے کہا.ایسا تو کوئی نہیں مگر ہاں میرا
بھائی جساس ہے اگر وہ اپنے منہ سے کوئی بات کہ بیٹھے تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا.“
اس کے بعد حلیلہ نے اپنی طرف سے اس جھگڑے کو روکنے کی بہت کوشش کی ، مگر کامیاب نہ ہوسکی
آخر ایک دن جب کلیب اپنے اونٹوں
کو پانی پلا رہا تھا، اتفا قاجناس بھی اوپر سے اپنے اونٹ لے آیا اور
مزید اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے گلے سے وہی سعد کی اونٹنی چھوٹ کر کلیب کے اونٹوں میں آ کر پانی پینے
لگ گئی.کلیب نے اسے دیکھا اور خیال کیا کہ جناس نے دیدہ دانستہ اسے چھوڑا ہے اس پر اس نے اپنی
کمان لی اور اس کے شیردان میں تیر مارا جو سیدھا اپنے نشانہ پر بیٹھا اور سعد کی اونٹنی تڑپتی اور چلاتی ہوئی
دوڑی اور جساس کی خالہ بسوس کے دروازے کے سامنے پہنچ کر گر گئی.بسوس نے یہ نظارہ دیکھ کر اپنا سر
پیٹنا شروع کر دیا.اور زور سے چلا چلا کر کہا.” شرم شرم ! ہم ذلیل کئے گئے اور ہمارے مہمان کی اونٹنی مار
دی گئی.جساس نے یہ الفاظ سنے تو شرم اور غیرت سے کٹ گیا اور غضب میں آ کر اس نے کلیب کو قتل کر
دیا.کلیب کے قتل نے قبیلہ تغلب میں آگ لگا دی اور اپنے سردار کے انتقام کے لئے وہ ایک جان ہو کر
اٹھ کھڑے ہوئے جس کے نتیجہ میں قبائل تغلب اور بکر میں وہ خطرناک لڑائیاں ہوئیں اور ا تنا قتل وخون ہوا
کہ خدا کی پناہ.آخر چالیس سال کے بعد جب دونوں قبائل کٹ کٹ کر کمزور ہو گئے تو ریاست حیرہ کے
بادشاہ مُنذ رثالث کے ذریعہ سے ان میں پھر صلح ہوئی.یہ جنگ تاریخ عرب میں جنگ بسوس کے نام سے
مشہور ہے.عرب کے جنگوں میں عام طور پر تاریعنی انتقام کا بڑا دخل ہوتا تھا.ٹار کا عقیدہ گویا عرب کے دین و
مذہب کا جز واعظم تھا.ان کا ایمان تھا کہ جب تک بدلہ نہ لے لیا جاوے مقتول کی روح ایک جانور کی
صورت اختیار کر کے ہوا میں نوحہ کرتی پھرتی ہے اس جانور کو عرب لوگ صدی کہتے تھے.جب کسی قبیلے کا
: تاریخ کامل ابن اثیر.
Page 78
۶۳
کوئی آدمی مارا جا تا تو اس کے رشتہ داروں اور اہلِ قبلہ کا یہ فرض ہو جا تا تھا کہ قاتل یا اس کے کسی رشتہ دار
یا اس کے قبیلہ کے کسی آدمی کو اس کے بدلے میں قتل کریں.مقتول کے بدلے میں دیت یعنی خون بہا لینے
کا بھی رواج تھا، مگر اس میں مالی پہلو اتنا متصور نہ تھا جتنا یہ کہ قاتل کا قبیلہ ذلیل اور شرمندہ ہو کر مقتول کا
خون بہا ادا کرے لیکن عموماً جب تک مقتول کا بدلہ قتل کے ساتھ نہ لے لیا جاتا.اس وقت تک اس کے
رشتہ داروں کے دلوں میں ایک آگ سی لگی رہتی تھی جسے صرف قاتل کا خون ہی بجھا سکتا تھا، لیکن جب
ایک طرف کی آگ بجھ جاتی تھی تو دوسری طرف یہی آگ بھڑک اٹھتی تھی اور اس طرح یہ سلسلہ ایسا وسیع
ہوتا چلا جاتا تھا کہ بعض اوقات قبیلے کے قبیلے اس میں بھسم ہو جاتے تھے.صرف قاتل کو مار دینے تک مقتول کا انتقام ختم نہ ہوتا تھا بلکہ مُردوں کے ہاتھ پاؤں کان ناک وغیرہ
کاٹ کر بھی اپنے دل کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا.اس طریق کو عربوں میں مثلہ کہتے تھے اور عرب کی جنگوں میں
اس کا عام رواج تھا.چنانچہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جنگِ اُحد میں ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ جنہوں نے جنگ بدر میں اس کے باپ عتبہ کو
قتل کیا تھا یہی سلوک کیا بلکہ نہایت بیدردی کے ساتھ آپ کا جگر نکال کر چبا گئی.عورتیں اور بچے جو جنگ
میں قید ہو کر آتے تھے ان کو قتل کر ڈالنے میں بھی عربوں کو دریغ نہ ہوتا تھا.انتقام پورا کرنے کے واسطے
مردوں کی کھوپڑیوں میں شراب پینا ، نیزہ مار کر حاملہ عورتوں کا حمل گرا دینا ، غفلت کی حالت میں
سوتے ہوئے آدمیوں پر حملہ کر کے ماردینا وغیر ذالک یہ ایسی باتیں تھیں جن کو عرب کی سوسائٹی
عموماً نا جائز نہیں سمجھتی تھی.جنگوں میں عرب کا دستور تھا کہ ایک اونچی جگہ پر آگ جلا دیتے تھے اور دورانِ جنگ میں اسے برابر
جلتا رکھتے تھے اور اس کے بجھ جانے کو بُری فال خیال کرتے تھے ؛ چنانچہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ
جب جنگ احزاب میں کسی وجہ سے ایک افسر کی آگ بجھ گئی تو وہ گھبرا کر رات کے وقت اکیلا ہی میدانِ
جنگ سے بھاگ نکلا جس کی وجہ سے باقی فوج میں بھا گڑ پڑ گئی.جنگ میں عموماً عورتیں بھی ساتھ جاتی تھیں جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ غیرت اور جوش دلانے کے شعر
پڑھ پڑھ کر آتش عرب
کو بھڑکاتی رہیں.زخمیوں کی نگہداشت بھی عموماً عورتیں ہی کرتی تھیں ؛ چنانچہ یہ رسم
ایک حد تک اسلام میں بھی قائم رہی.لڑائی میں یہ عام دستور تھا کہ پہلے ایک ایک آدمی کا انفرادی مقابلہ ہوتا تھا اور پھر عام دھاوا ہو جاتا
Page 79
۶۴
تھا.جنگ میں عرب لوگ عموماً تین قسم کے ہتھیار استعمال کرتے تھے.تیر کمان ، نیزہ اور تلوار.بچاؤ کے
واسطے زرہ اور خود استعمال کی جاتی تھیں.عرب لوگ جنگ گھوڑے پر بھی کرتے تھے اور پیدل بھی.لیکن
بہادروں کے درمیان یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ لڑائی کے وقت گھوڑے سے اتر کر اپنے عزیز
گھوڑے کی کونچیں کاٹ کر اسے نیچے گرادیں تا کہ یہ ثابت ہو کہ ہم نے اپنے واسطے بھاگنے کا کوئی راستہ کھلا
نہیں رکھا.جنگوں میں بار برداری کے لیے اونٹ استعمال ہوتا تھا.عربوں میں بہادری اور شجاعت نہایت اعلیٰ وصف سمجھے جاتے تھے اور عرب شاعر اپنی اور اپنے قبیلہ
کی بہادری کے کارنامے دلی جوش و خروش کے ساتھ منظوم کرتے تھے اور بہادری گویا ان کے قومی خصائل
میں سب سے نمایاں تھی.موت کے ڈرکو ایک سخت قابل شرم بات خیال کیا جاتا تھا اور موت سے ڈرنے
والا سب کی نظروں میں مطعون ہو جاتا تھا.دراصل بہادری عربوں کی زندگی کے ساتھ لازم وملزوم تھی.عربوں کی غیرت اور غرور کے قصے بھی بہت مشہور ہیں.عمرو بن کلثوم کا مشہور مُعلَّقہ جس میں وہ
عمر و بن ہند کو خاص عربی انداز میں مخاطب کرتا ہے، عربوں کی غیرت کی ایک عام مثال ہے.عموماً عرب
لوگ اپنے مفاد کے مقابلہ میں عہد و پیمان کا زیادہ پاس نہ کرتے تھے ، تاہم عربوں کے اندر وفاداری کی
بعض مثالیں حیرت انگیز ہیں.شموئل بن عادیہ نے امرؤ القیس کی امانت کی حفاظت میں اپنے جوان بیٹے
کے قتل کی پروانہیں کی.عربوں میں سخاوت ایک نہایت اعلیٰ وصف سمجھا جاتا تھا اور پڑوسی اور مہمان کی حفاظت ان کے
دین و مذہب کا حصہ تھی.مہمان نوازی تو عربوں کی فطرت میں تھی.رات کو کسی اونچی جگہ آگ جلا رکھتے
تھے تا کہ اسے دیکھ کر مصیبت زدہ مسافران تک پہنچ سکے.مہمان کی خاطر گھر کا سب کچھ خرچ کر ڈالنے
میں دریغ نہ تھا.اس ضمن میں عرب کے مشہور ہیر و حاتم طائی کی سخاوت و مہمان نوازی کے قصے زبان
زدخلائق ہیں.قبیلہ کی پاسداری عربوں کا فرض عین تھا.ایک شاعر فخر یہ کہتا ہے کہ میں تو قبیلہ غزیہ سے ہوں.اگر وہ
غلطی کریں تو میں بھی غلطی کروں گا اور اگر غز یہ ٹھیک راستہ پر چلیں تو میں بھی ٹھیک راستہ پر چلوں گا.عرب میں اپنے حسب نسب پر فخر کرنے کی عادت عام تھی اور اپنے باپ دادوں کے کارناموں کا
فخریہ لہجہ میں ذکر کرنا ان کا خاصہ تھا.یہ اسی تکبر کا نتیجہ تھا کہ عرب لوگ غلاموں اور خادموں کو نہایت
ل : دیوان الحماسه
Page 80
حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے.دشمن کے ساتھ معاملہ کرنے میں عرب لوگ عموماً ظالم اور سخت گیر تھے.ثار کا خونی عقیدہ اوپر بیان ہو
چکا ہے.یہ گویا عرب کے دین و مذہب کا ئجز واعظم تھا.تار کے مقابلہ میں خدائی قضاء وقدر کی بھی پروانہ
تھی ایک شاعر کہتا ہے:
سَاغُسِلُ عَنِّي الْعَارَ بِالسَّيْفِ جَالِبًا عَلَى قَضَاءُ اللَّهِ مَا كَانَ جَالِبًا
میں اپنے اوپر سے شرم و عار کو ضرور تلوار کیسا تھ دھووں گا، پھر اللہ کی قضاء مجھ پر جو چاہے لاوے
مجھے پروانہیں لے
عرب لوگ نہایت ذکی اور ذہین تھے اور ان کا حافظہ غضب کا تیز تھا چنانچہ قدیم سے ان کا دستور تھا
کہ اپنی تمام قومی اور خاندانی روایت کو یا در رکھتے تھے اور مختلف موقعوں پر سناتے رہتے تھے.جنگ میں
جب دو جانباز سپاہی مقابلہ کے واسطے آگے بڑھتے تھے تو پہلے ایک دوسرے کا حسب نسب ضرور دریافت
کرتے تھے اور اگر کوئی نیچ ذات کا ہوتا تھا تو اس کو اپنے مقابلہ میں آنے کی اجازت نہ دیتے تھے.عربوں میں سال اور ماہ چاند کی گردش کے حساب سے شمار کئے جاتے تھے اور بارہ مہینوں میں سے
پہلا، ساتواں اور آخری دو مہینے عزت کے مہینے سمجھے جاتے تھے جن میں ہر
قسم کا قتال ممنوع تھا، لیکن بعض
اوقات اپنی سہولت کے واسطے عرب انہیں آگے پیچھے بھی کر لیتے تھے تا کہ اگر کوئی ضرورت آ پڑے تو ان
مہینوں میں بھی بلاخوف گناہ جنگ وجدال کر سکیں.اس رسم کونسی کہتے تھے.عورت کی حیثیت عرب میں عورت کی حالت بحیثیت مجموعی اچھی نہ تھی.بیشک عموماً عورت کو اپنا
خاوند خود انتخاب کرنے کا اختیار تھا مگر اس اختیار کے بعد وہ عملاً بے اختیار تھی.ہاں ہوشیار عورتیں اپنے خاوندوں پر اچھا اثر رکھتی تھیں.جنگ میں عورتوں کے ساتھ جانے کا بیان کیا جا
چکا ہے.ان کا کام مردوں کو غیرت دلانا اور زخمیوں کی خبر گیری کرنا تھا.عور تیں شعر بھی کہتی تھیں ؛ چنانچہ
خنساء زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور شاعرہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوگئی تھی سکے
عورتوں میں پردے کی رسم نہ تھی بلکہ وہ کھلی پھرتی تھیں.تعدد ازدواج کی کوئی حد نہ تھی اور جتنی
بیویاں کوئی شخص رکھنی چاہتا تھار کھتا تھا.بعض اوقات باپ کی منکوحہ پر بیٹا وارث کے طور پر قبضہ کر لیتا تھا
اور دو حقیقی بہنوں سے بھی ایک وقت میں شادی کر لیتے تھے.مگر ان باتوں کو اشراف عرب اچھی نظر سے نہ
: دیوان الحماسه
: ابن ہشام
: اسد الغابه
Page 81
۶۶
دیکھتے تھے.عرب میں طلاق کا عام رواج تھا اور خاوند جب چاہتا بیوی کو الگ کر سکتا تھا.لڑکیوں کو زندہ
دفن کر دینے کی رسم بھی عرب میں تھی.مگر یہ رسم خاص خاص قبائل میں تھی.عام نہ تھی.لڑکیوں
کو ورثہ نہ ملتا تھا اور نہ ہی بیوی کوشنی کہ اگر کسی شخص کی نرینہ اولا د نہ ہوتی تھی تو اس کے مرنے
پر سب تر کہ اُس کا بھائی لے جاتا تھا اور اس کی بیوی اور لڑکیاں یونہی خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں.رسوم اور رسوم پرستی یہ ابھی بیان کیا جائے گا کہ ظہور اسلام کے وقت عرب میں بہت سے مذاہب
پائے جاتے تھے.جو مختلف عقائد اور مختلف خیالات کے پیرو تھے.لیکن
عادات اور قومی اخلاق کے لحاظ سے تمام عرب گویا ایک قوم کے حکم میں تھا اور جو جو عادات اور اخلاق ہم
نے اوپر بیان کی ہیں وہ سب میں نمایاں طور پر پائی جاتی تھیں؛ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں یثرب میں ایک
یہودی رئیس فطیون تھا اس
کمبخت کا یہ عام حکم تھا کہ شہر میں جس لڑکی کی بھی شادی ہو وہ پہلے اس کے گھر میں
آوے.چنانچہ مدینہ کے اکثر یہودی اپنی ناکتخد الڑکیاں شادی کے وقت پہلے اس کے گھر بھیجتے تھے اور اس
کے بعد وہ کسی اور کے واسطے جائز ہوتی تھیں.آخر ایک غیرت مند شخص نے فطیون
کو قتل کر ڈالا.اسی
طرح اس زمانہ میں عیسائیوں کی حالت بھی بہت خراب تھی جیسا کہ میور صاحب نے بھی اپنی کتاب میں
تسلیم کیا ہے.غرض عرب میں کیا بت پرست، کیا یہودی اور کیا نصاری سب اخلاق و عادات اور قوی
خصائل کے لحاظ سے ایک ہی رنگ میں رنگین تھے اور قتل و غارت اور قمار بازی ، زنا ، شراب خوری کا بازار
ہر طرف گرم تھا.اسی طرح رسوم کی پابندی بھی سب میں مشترک تھی اور رسوم پرستی اس درجہ کی تھی کہ مذہب بھی اس
کے سامنے بیچ تھا.عجیب عجیب رسوم ملک میں پھیلی ہوئی تھیں مثلاً ایک تقسیم بالازلام کی رسم تھی.یعنی ایک
قربانی میں دس لوگ حصہ ڈالتے تھے اور پھر اس کی تقسیم حصہ رسدی سے نہ کرتے تھے بلکہ قربانی کے تیروں
سے ایک قسم کا قرعہ ڈالا جاتا تھا اور پھر اس طرح جو جو کسی کا حصہ نکلتا تھا وہ اسے مل جاتا تھا اور بعض خالی بھی
رہ جاتے تھے.ہر تیر کا نام اور الگ الگ حصہ مقرر ہوتا تھا.تیروں سے فال لینے کی رسم بھی عام تھی.ہر کام کرتے ہوئے تیر سے فال لیتے تھے.کعبہ میں بھی
فال کے تیر رکھے ہوئے تھے اور وہاں جا کر لوگ فال نکالتے تھے.پرندوں کی اڑان سے بھی فال لینے
ل : وفاء الوفاء بحوالہ سیرۃ النبی
: لائف آف محمد (ع ) دیبا چه صفحه ۸۳ و اصل کتاب صفحه ۲۰
Page 82
کا دستور تھا.۶۷
ایک عجیب رسم عرب کے بعض قبائل میں یہ تھی کہ جب کسی سفر کے ارادے سے گھر سے نکلتے تھے تو اگر
راستہ میں کسی وجہ سے واپس آنا پڑتا تھا ، تو دروازوں کے ذریعہ اندر نہ داخل ہوتے تھے بلکہ پشت کی
طرف سے آتے تھے.قرآن شریف میں بھی اس کی طرف اشارہ آتا ہے.بعض قبائل میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے پاس اس کے اونٹ کو باندھ
دیتے تھے حتی کہ وہ بھوک پیاس سے مرجاتا تھا.عورتوں میں سخت نوحہ کرنے کی عادت تھی.سال سال
تک ما تم چلا جاتا تھا.عرب میں بالعموم عورتیں جانوروں کا دودھ
نہ دوہتی تھیں اور اسے عورت کے لیے ایک عیب سمجھا جاتا
تھا.اگر کسی خاندان میں کوئی عورت ایسا کرتی دیکھی جاتی تھی تو وہ خاندان دوسروں کی نظروں میں گر
جاتا تھا.جانوروں کو بتوں وغیرہ کے نام پر یا کسی نذر وغیرہ کے نتیجہ میں آزاد چھوڑ دینے کی بھی رسم تھی اور اس
تعلق میں چار قسم کے جانور زیادہ معروف تھے.اوّل سائبہ ایسی اونٹنی کو کہتے تھے جس نے پے در پے دس
مادہ بچے جنے ہوں ایسی اونٹنی پر سواری ترک کر دی جاتی تھی اور اس کا دودھ بھی سوائے مہمانوں کے
استعمال کے حرام سمجھا جاتا تھا اور اس کی اون بھی نہیں کائی جاتی تھی.دوسرے بحیرہ جو سائبہ اونٹنی کے
گیارھویں مادہ بچہ کو کہتے تھے.بحیرہ کو اس کے کان درمیان میں کاٹ کر اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ
دیا جاتا تھا.تیسرے حام : ایسے اونٹ کا نام رکھا جاتا تھا جو اوپر تلے دس بچوں کا باپ ہو ، اسے سانڈ کے
طور پر کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا.چوتھے وصیلہ: ایسی بکری کو کہتے تھے جو پانچ جھولوں میں مسلسل دس مادہ بچے
جنتی تھی.ایسی بکری کی بعد کی اولاد کا گوشت صرف مرد کھاتے تھے عورتوں کے لیے حرام تھا.البتہ اگران
میں سے کوئی بچہ مرجاتا تھا تو اس کا گوشت عورتیں بھی کھا سکتی تھیں.قرآن شریف میں بھی ان جانوروں
کا ذکر آتا ہے.نکاح کے متعلق بھی عجیب عجیب رسوم رائج تھیں.عموماً نکاح کی صورتیں چار تھیں جن میں سب سے
عجیب اور سب سے گندی صورت یہ تھی کہ ایک عورت کے پاس یکلخت چند آدمی پہنچ جاتے تھے اور وہاں
یکے بعد دیگرے اپنا منہ کالا کرتے تھے اور جب وہ کوئی بچہ جنتی تھی تو پھر یہ لوگ دوبارہ اس کے پاس جمع
ل : سورة البقرة : ١٩٠
سیرت ابن ہشام وسورة انعام
: سورۃ مائده آیت : ۱۰۴
Page 83
۶۸
ہوتے تھے اور وہ عورت جس شخص کے متعلق کہہ دیتی تھی کہ بچہ اس کا ہے، اسی کی طرف وہ منسوب ہوتا تھا.مگر شرفاء کا دامن اس قسم کی بے حیائیوں سے پاک تھا.لے
یہ چند رسوم صرف مثال کے طور پر لکھی گئی ہیں ورنہ عرب میں رسوم کی بے حد کثرت تھی اور عجیب
عجیب رسومات کا وجود پیدا ہو گیا تھا.اسلام نے سب گندی رسوم کو یک قلم منسوخ کر دیا.قدیم مذاہب عرب عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب کے پیر و پائے جاتے تھے ، جن میں
سے زیادہ ممتاز بت پرست ، دہریہ، مجوسی ، صابی ، عیسائی اور یہودی تھے.ان
مذاہب میں سب سے زیادہ عام اور سارے ملک میں پھیلا ہوا بُت پرستی کا مذہب تھا جسے گویا ملک کا اصل
مذہب کہنا چاہیے.بُت پرست اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بھی قائل تھے ، مگر اس تک پہنچنے کا وسیلہ بتوں کو سمجھتے
تھے لیکن اس درمیانی واسطہ میں وہ ایسے الجھے ہوئے تھے کہ اصل معبود کا خیال دل سے نکل گیا تھا.مشترک
بتوں کے علاوہ عموماً ہر قبیلہ کا اپنا اپنا خاص بت بھی تھا.چنانچہ مکہ میں اساف اور نائکہ قریش کے بت تھے،
جن کے سامنے قربانیاں ذبح کی جاتی تھیں.عزتی نخلہ میں قریش اور بنو کنانہ کا مشتر کہ بت تھا.طائف
میں لات بنو ثقیف کا بت تھا.منات اوس اور خزرج کا بت تھا.دومۃ الجندل میں ڈر بنو کلب کا بت تھا.قبیلہ ھذیل کا بُت سواع تھا.یغوث قبائل مذحج اور مکی کا بت تھا.نسر ذوالکلاع کا بت تھا اور یعوق یمن
میں ہمدان کا بت تھا وغیرہ وغیرہ.سب سے بڑا بت قبل تھا جو کعبہ میں نصب تھا.جنگ میں فتح کے موقع
پر اسی کے نام کے نعرے لگتے تھے.عرب کے بُت پرستوں کا مذہبی مرکز کعبہ تھا.جہاں انہوں نے بہت سے بُت جمع کر رکھے تھے.کے
اور عرب کے مشرک لوگ ملک کے تمام حصوں سے ہر سال حج کے واسطے مکہ میں جمع ہوتے تھے.یہ گویا
ابرا ہیمی تعلیم کی ایک بقیہ نشانی تھی ، مگر مراسم حج میں بھی ان لوگوں نے کئی قسم کی مشر کا نہ باتیں شامل کر لی
تھیں جو اسلام نے خارج کر دیں.مکہ کی اس مذہبی خصوصیت کی وجہ سے مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ حرم
کا علاقہ تھا جہاں ہر قسم کا کشت و خون سخت ممنوع تھا.اسی طرح حج اور عمرہ کے لیے لوگوں کی آمد ورفت میں
سہولت پیدا کرنے کی غرض سے سال میں چار مہینے یعنی محرم ، رجب، ذیقعدہ ، ذی الحجہ خاص عزت کے
مہینے سمجھے جاتے تھے جن میں کشت و خون رک جاتا تھا اور لوگ امن کے ساتھ اِدھر اُدھر آ جا سکتے تھے.بُت پرستی کے علاوہ عرب میں دہریت بھی تھی.اس کے پیر وخدا کی ہستی ، بعث بعد الموت ، جزا سزا
: بخاری کتاب النکاح
: ابن ہشام
: بخاری کتاب و جوب الحج
Page 84
۶۹
وغیرہ کے قائل نہ تھے.قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے.پھر عرب میں مجوسی بھی تھے جو آتش پرست اور ستارہ پرست تھے، مگر یہ لوگ خدا کی ہستی کے بھی قائل
تھے اور عبادات کا بھی ان کے مذہب میں دستور تھا.محققین کا خیال ہے کہ یہ مذہب جو اپنی اصل کے لحاظ
سے ایرانی ہے درحقیقت الہامی مذاہب میں سے تھا مگر آہستہ آہستہ بگڑ گیا.قرآن شریف میں بھی اس کا
ذکر آتا ہے.موجودہ پارسی قوم اسی مذہب کی تابع ہے.ایک مذہب صابی تھا جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آتا ہے.یہ مذہب مجوسیت اور یہودیت کا
مجموعہ تھا.مگر معلوم ہوتا ہے کہ عرب لوگ عام طور پر صابی کا لفظ ہر اس شخص پر بول دیتے تھے جس نے اپنا
قدیم مذہب ترک کر کے توحید سے ملتا جلتا مذہب اختیار کر لیا ہو چنانچہ بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم اور صحابہ کو بھی صابی کہہ کر پکارتے تھے.عیسائیت عرب میں ظہور اسلام سے بہت عرصہ پہلے داخل ہو چکی تھی اور بعض قبائل اسے اختیار کر
چکے تھے.عرب میں نجران کا علاقہ اس مذہب کا بڑا مرکز تھا.عرب کے یہودی ابتداء شام کی طرف سے آئے تھے اور پھر اس کی اتباع میں بعض دوسرے قبائل
بھی یہودی بن گئے تھے.یہود کے بڑے مرکز یثرب، خیبر اور تیما تھے.ایک مذہب اور تھا جو حضرت ابرا ہیم کی طرف منسوب ہوتا تھا اور توحید کا مدعی تھا اس کا نام بعض
لوگوں نے مذہب حنیفی رکھا ہوا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوائل زمانہ میں اور اس سے کچھ پہلے
بعض لوگ عرب کی انتہائی بت پرستی سے متنفر ہو کر اور آفتاب رسالت کی طلوع کرنے والی کرنوں کی پیشگی
طور پر روشنی پاتے ہوئے اس مذہب کی طرف مائل تھے مگر ان کی تعداد تمام عرب میں چند نفوس سے زیادہ
نہ تھی اور یہ لوگ قریباً سب کے سب مکہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والے تھے.حضرت عمر کے چچا زاد
بھائی زید بن عمر و جن کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تعلقات تھے انہی لوگوں میں سے تھے،
مگر بعثت نبوی سے پہلے ہی انکا انتقال ہو گیا.سعید بن زید جو مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ،
انہی کے صاحبزادے تھے.زید کو بُت پرستی سے اس درجہ نفرت تھی کہ وہ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہ کھاتے
تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جنہیں تم پوجتے ہوئے طائف میں اُمیہ بن ابی صلت
ایک مشہور شاعر اور معزز رئیس تھا وہ بھی بُت پرستی ترک کر کے مذہب حنیفی اختیار کر چکا تھا.اُمیہ جنگ بدر
ل : سورۃ حج آیت : ۱۸
: بخاری حدیث زید بن عمر و
Page 85
کے بعد تک زندہ رہا مگر اسلام لانا اس کی قسمت میں نہ تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
بڑے شوق سے اس کے مواحدانہ اشعار سُنے اور افسوس کے ساتھ فرمایا کہ امیہ مسلمان ہوتے ہوتے
رہ گیا.ایک اور شخص ورقہ بن نوفل تھا جو حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی تھا اور مکہ میں رہتا تھا.یہ بُت پرستی
ترک کر کے بعد میں عیسائی ہو گیا تھا اور توریت و انجیل سے واقف تھا اور ان کا مطالعہ رکھتا تھا، مگر جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الہی فرشتہ نازل ہوا تو اس نے آپ کی تصدیق کی اور اسی تصدیق کی حالت
میں فوت ہوا.ایک شخص قس بن ساعدہ جو بکر بن وائل کے علاقہ میں رہتا تھا اور نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھا چنانچہ
بعثت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عکاظ کے میلے میں اس کا ایک خطبہ سنا تھا؛ چنانچہ ایک
دفعہ آپ زمانہ نبوت میں فرماتے تھے کہ میں نے عکاظ میں قس بن ساعدہ کا ایک خطبہ سُنا تھا جو اس نے
اونٹ پر چڑھے چڑھے دیا تھا اور آپ اس کی فصاحت کی تعریف فرماتے تھے.قفس بھی شرک ترک
کر کے توحید اختیار کر چکا تھا مگر اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گیا کے
ایک اور شخص عثمان بن حویرث تھا.یہ مکہ کا رہنے والا تھا اور بت پرستی ترک کر کے دین حنیفی کا متبع ہو
گیا تھا، لیکن بعد میں جب وہ قیصر روم کے دربار میں پہنچا تو عیسائی ہو گیا اور اسی مذہب پر اس کی وفات
ہوئی.یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے.غرض عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب پائے جاتے تھے مگر باوجود ان مختلف مذاہب کے
عرب کا اصل اور عام مذہب بُت پرستی تھا اور دوسرے لوگ اتنے بھی نہ تھے جیسے آٹے میں نمک اور وہ بھی
سخت بگڑی ہوئی اور نا کامی کی حالت میں تھے جیسا کہ خود یورپین مؤرخین کو بھی اقرار ہے؛ چنانچہ قدیم
مذہب عرب پر ریویو کرتے ہوئے سرولیم میور لکھتے ہیں :
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی جوانی کے زمانہ میں عرب ایک بندھی لیک پر چلنے
والے لوگ تھے اور ملک کی حالت ہر قسم کے تغیر واصلاح کے سخت مخالف تھی بلکہ اس
کی تمام تاریخ میں شاید اس زمانہ سے بڑھ کر کوئی ایسا زمانہ نہیں گذرا کہ جب اس کی
لے : شمائل ترمذی
: سيرة حلبیہ جلد ۱ صفحه ۱۳۸
: بخاری
س : اصابه ذکر قس بن ساعدہ قسم ۴
Page 86
اے
ہو
اصلاح اس وقت سے زیادہ مشکل اور مایوس کن ہو....عیسائی مذہب کی پانچ سو
سال کی تبلیغی کوششوں کا یہی نتیجہ تھا کہ ملک میں خال خال عیسائی نظر آتے تھے اور
بس.یہودی مذہب زیادہ طاقتور تھا.لیکن ایک تبلیغی مذہب کے طور پر وہ بھی اب گویا
بالکل رہ چکا تھا، لیکن بُت پرستی اور بنو اسمعیل کے تو ہمانہ اعتقادات کا دریا ہر سمت سے
جوش مارتا ہوا کعبہ کی دیواروں سے آ آ ٹکراتا تھا.یہ حالت صرف عرب ہی کی نہ تھی بلکہ یہ وقت ساری دنیا پر ایک سخت تاریکی کا وقت تھا اور تمام
مذاہب بگڑ چکے تھے اور گمراہی چاروں طرف اپنا دامن پھیلائے ہوئے تھی.اسی طرف یہ آیت قرآنی
اشارہ کرتی ہے کہ:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
د یعنی اس وقت خشکی اور تری ہر دو میں فساد ظاہر ہو چکا ہے“
یعنی الہام الہی پر بنیا درکھنے والے مذاہب بھی خراب ہو چکے ہیں اور وہ مذاہب بھی جن کی بنیاد الہام
پر نہیں ہے.اب دیکھو کہ جب دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے تو سورج نکلتا ہے اور جب زمین تپ جاتی ہے تو
وہ بارش کو بھینچتی ہے تو روحانی اندھیرے کے بعد روحانی سورج نہ نکلتا ؟ اور کیا روحانی زمین کی تپش روحانی
بارش کو نہ کھینچتی ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
نیز فرماتا ہے:
يُقَلِبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ -
و یعنی اللہ تعالیٰ رات اور دن کی حالت کو آپس میں بدلتا رہتا ہے
اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا :
جان لو! اس وقت وہ زمین کو زندہ کر رہا ہے بعد اس کے کہ وہ مرچکی تھی،
پس نا گہاں اس تاریکی کے زمانہ میں ایک سورج نکلا جس نے اپنی شعاعوں سے اطراف عالم میں
اُجالا کر دیا اور اس شدید گرمی کے وقت میں اچانک ایک بادل اُٹھا جس نے پیاسی زمین پر رحمت کی
ا: دیباچہ لائف آف محمد صفحه ۸۴ ، ۸۵
۳ : سورة نور: ۴۵
ے : سورة روم: ۴۲
: سورة حديد : ۱۸
Page 87
۷۲
بارشیں برسائیں اور ندی نالے جو خشک پڑے تھے پانی سے بہہ نکلے.یہ سورج کس اُفق سے طلوع ہوا اور
کس طرح نصف النہار پر پہنچا اور یہ بادل کس دامن کوہ سے اُٹھا اور کس طرح ساری دنیا پر چھا گیا؟ ان
سوالات کا جواب انشاء اللہ ذیل کے اوراق میں ملے گا.وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهُ
Page 88
۷۳
مکہ کعبہ اور قریش
ابوالانبیاء
خلیل اللہ حضرت
ابراہیم کا نام نامی کسی معرفی کا محتاج نہیں.کون ہے جو ابوالانبیاء خلیل اللہ
کو نہیں جانتا.مسلمان، عیسائی، یہودی کبھی ان کو مانتے ہیں.آپ کا زمانہ
موٹے طور پر اکیس بائیس سو سال قبل مسیح قرار دیا گیا ہے.یعنی آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً
ستائیس اٹھائیس سو سال پہلے گزرے ہیں.آپ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور عراق کے
رہنے والے تھے مگر بعد میں مصر وغیرہ میں سے ہوتے ہوئے بالآ خرجنوبی فلسطین میں آباد ہو گئے.آپ
نے تین شادیاں کیں.پہلی بیوی کا نام سارہ تھا.دوسری کا نام ہاجرہ تھا.اور تیسری کا نام قطورا.ان میں
سے مؤخر الذکر کے ذاتی حالات زیادہ معلوم نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں اس جگہ ان سے تعلق ہے مگر اس قدر ذکر
غیر مناسب نہ ہو گا کہ وہ قوم مدین کی نسل سے تھی.حضرت ابراہیم کی پہلی دو بیویوں میں سے سارہ حضرت
ابراہیم کے قریبی عزیزوں میں سے تھیں مگر ہاجرہ ایک غیر خاندان سے تھیں اور مصر کی رہنے والی تھیں.ان دونوں کے بطن سے اولاد ہوئی اور اس قدر پھیلی کہ آج دُنیا کے ہر گوشہ میں پائی جاتی ہے.حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسمعیل پیدا ہوئے جو حضرت ابراہیم کے بڑے لڑکے تھے.اور حضرت
سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے.یہ دونوں بچے خُدا کی خاص بشارات کے ماتحت پیدا ہوئے تھے اور دونوں
کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت کے وعدے تھے.یا اور اُن کے نام بھی خدائی الہام کے
ماتحت رکھے گئے تھے.اور اسمعیل کے متعلق تو حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کی خاص دُعا بھی تھی.کے
جیسا کہ اُن کا نام بھی جو دراصل سمع ایل ہے.یہ ظاہر کرتا ہے؛ چنانچہ ان دونوں بچوں کو خدا تعالیٰ نے
: پیدائش باب ۱۶ آیت اور باب ۱۷ آیت ۲۰ و باب مذکور آیت ۱۹،۱۶
: پیدائش باب ۱۶ آیت ا او باب ۱۷ آیت ۱۹
۳ : قرآن شریف سورۃ صافات آیت ۰۲ او پیدائش باب ۱۱۲ آیت ۱۱ ے : یعنی خدا نے دُعاسُن لی
Page 89
۷۴
عظیم الشان برکات کا وارث بنایا اور حسب وعدہ ان دونوں کی نسل کو دُنیا میں ہر قسم کے انعام سے مالا مال
کیا.چنانچہ بنواسرائیل جن میں حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت مسیح ناصری
جیسے عالی مرتبہ نبی پیدا ہوئے.حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں.مگر اس جگہ ہمارا تعلق بنو اسماعیل سے ہے
جو عرب میں آباد ہوئے اور جن سے فخر اولین و آخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود با جود نکلا.سکونت حجاز اور مکہ کی آبادی اسمعیل" ابھی بچہ ہی تھے کہ اُن کی سوتیلی ماں سارہ نے کسی بات پر
ناراض ہو کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو
گھر سے نکال دو.حضرت ابرا ہیم کو طبعا اس قول پر بہت رنج پیدا ہوا.مگر خدا تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم
سے فرمایا کہ رنجیدہ مت ہو اور اس بات کو بُرا نہ جان بلکہ جیسے سارہ کہتی ہے ویسے ہی کر.اسحاق بھی تیری
اولاد ہے مگر مجھے ہاجرہ کے فرزند اسمعیل سے ایک قوم بنانا ہے.چنانچہ اس الہی ارشاد کے ماتحت حضرت
ابراہیم نے سینکڑوں میل کا سفر اختیار کر کے حضرت اسمعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو عرب کے علاقہ حجاز کے
اندر وادی بکہ میں لا کر آباد کیا.یہ وہ وادی ہے جہاں اب مکہ آباد ہے.اُس وقت یہ ایک بالکل غیر آباد
اور ویران وادی تھی.اس وادی میں صفا اور مروہ کی گھاٹیوں کے پاس ان دو بے کس اور بے بس جانوں کو
تھوڑے سے زاد کے ساتھ جنگل میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم اپنے وطن کو واپس روانہ ہوئے.حضرت
ابراہیم کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ اُن کے پیچھے پیچھے آئیں اور نہایت درد آمیز الفاظ میں کہنے لگیں
”آپ کہاں جاتے ہیں اور ہم کو اس طرح کیوں اکیلا چھوڑ کر جارہے ہیں؟“ حضرت ابراہیم خاموشی کے
ساتھ قدم بڑھاتے گئے اور کوئی جواب نہ دیا.آخر ہاجرہ نے کہا.آپ
کچھ تو بولیں ” کیا خُدا نے آپ سے
ایسا فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ”ہاں اور پھر خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے گئے.اس پر ہاجرہ
بولیں.اگر اللہ کا حکم ہے، تو پھر آپ بے شک جائیں.اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا.“ یہ کہہ کر ہاجرہ
واپس لوٹ آئیں یہ قرآن شریف میں اس واقعہ کا حضرت ابراہیم کے ان الفاظ میں ذکر آتا ہے:
رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ
رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلوةَ فَاجْعَلْ أَفْبِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمُ
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ
: پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۲ ،۱۳ و میس جلد اصفحه ۱۰۵
: ابراهیم : ۳۸
بخاری و تاریخ خمیس
Page 90
۷۵
یعنی جب حضرت ابراہیم " ہاجرہ اور اسمعیل کو وادی مکہ میں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو انہوں نے
تھوڑی دُور جا کر پیچھے نظر ڈالی اور خدا کے حضور یوں دُعا کی کہ:
”اے ہمارے رب ! میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو اس غیر آباد نجر وادی میں تیرے
عزت والے گھر کے پاس بسایا ہے.اے ہمارے رب ! میں نے یہ کام اس لئے کیا ہے کہ تا وہ
تیری عبادت کو قائم کریں اور تیرے لیے ان کی زندگی وقف ہو.پس تو لوگوں کے دل ان کی
طرف جھکا دے اور ان کو اچھے اچھے ثمرات کا رزق عطا کرتا کہ وہ تیرے شکر گذار ہوں.“
عام مؤرخین بیان کرتے ہیں اور حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ کا زاد ختم ہو گیا تو
لوازمات بشری کے تحت ان کو اپنے بیٹے کے متعلق سخت فکر پیدا ہوا اور وہ ادھر اُدھر پانی کی تلاش میں
پھریں ، مگر پانی کی ایک بوند تک نہ ملی اور بچے کی حالت پیاس سے جلد جلد ابتر ہوئی گئی.آخر ہاجرہ سے
اسمعیل کی حالت زار دیکھی نہ گئی ، اس لیے وہ وہاں سے اُٹھیں تاکہ اپنے بچے کی پیاس کی موت کو نہ دیکھیں
اور آسمان کی طرف منہ کر کے روئیں اور پانی کی تلاش میں پھر ادھر اُدھر بھا گئیں اور اردگرد کے علاقہ پر
اچھی طرح نظر ڈالنے کی غرض سے صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں لیکن وہاں سے بھی جب کوئی چیز نظر نہ آئی تو
بھاگتی ہوئی مروہ کی پہاڑی پر آئیں.وہاں سے پھر دوڑتی ہوئی صفا کی طرف گئیں اور اس طرح اُنہوں
نے ایک نہایت گھبراہٹ اور بیتابی کی حالت میں ان پہاڑیوں پر سات چکر لگائے اور ساتھ ساتھ زار زار
روتی بھی جاتی تھیں اور اللہ سے دُعا بھی کرتی جاتی تھیں.مگر نہ تو کوئی پانی کا پتہ ملتا تھا اور نہ ہی کوئی آدمی
نظر آتا تھا.آخر جب ہاجرہ کا کرب
انتہا کو پہنچ گیا تو ساتویں چکر کے بعد ہاجرہ کو ایک غیبی آواز سنائی دی
کہ اے ہاجرہ اللہ نے تیری اور تیرے بچے کی آواز سُن لی ہے.یہ آوازسُن کر وہ واپس آئیں تو جس
جگہ بچہ شدت پیاس کی وجہ سے بے تابی کی حالت میں تڑپ رہا تھا وہاں ایک خدائی فرشتہ کو کھڑا پایا جو اپنے
پاؤں کی ایڑی اس طرح زمین پر ماررہا تھا کہ گویا کوئی چیز کھود کر نکال رہا ہے.حضرت ہاجرہ آگے بڑھیں تو
جس جگہ وہ ایڈی مار رہا تھا وہاں اُنہوں نے ایک چشمہ پایا جس میں سے پانی پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا.ہاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی.اُس نے فوراً اپنے بچے کو پانی دیا اور اس خوف سے کہ پانی ضائع نہ ہو جاوے
اس کے گرد پتھر رکھ دیئے اور اسے ایک حوض کی صورت میں بنا دیا.حضرت ابنِ عباس سے روایت ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدا ہاجرہ پر رحم کرے.اگر وہ اس پانی کو نہ روکتی تو وہ ایک بہنے
والا چشمہ ہو جاتا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا
Page 91
۷۶
ہاجرہ ہی کی مقدس یاد گار ہے.ان واقعات کی ایک اجمالی اور کسی قدر محرف و مبدل نقشہ بائیبل میں بھی
مذکور ہے.حضرت ہاجرہ کی مقدس یاد گار کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاس تھا کہ ایک دوسری روایت سے
پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب خُدا تمہارے ہاتھ پر مصر کا ملک فتح کرائے تو
اہلِ مصر سے نیکی اور احسان کا سلوک کرنا کیونکہ بوجہ ہماری ماں ھاجرہ کے ( جو مصری تھیں ) تم پر اہلِ
مصر کا خاص حق ہے.بہر حال حضرت ابراہیم کے حضرت ہاجرہ اور اسمعیل کو مکہ کی ویران آبادی میں
آبادکر کے واپس چلے جانے پر ایک غیبی چشمہ کا وجود ظہور میں آیا اور اس کے بعد اس چشمہ کی وجہ سے جو
اسلامی تاریخ میں چاہ زمزم کے نام سے مشہور ہے وادی بلکہ میں اور لوگ بھی آباد ہونے لگے اور مکہ کی
آبادی شروع ہوئی.لکھا ہے کہ اس جگہ سب سے پہلے آباد ہونے والا قبیلہ جرھم تھا جو بنو قحطان کی ایک
شاخ تھا.یہ قبیلہ یمن سے آیا تھا اور پہلے وادی بکہ سے کچھ فاصلے پر آباد تھا.لیکن جب اُن کو زمزم کے
وجود سے اطلاع ہوئی تو ان کے رئیس مضاض بن عمر و جرہمی نے حضرت ہاجرہ سے چشمہ کے پاس ڈیرہ
لگانے کی اجازت چاہی.حضرت ہاجرہ نے بخوشی اجازت دے دی اور اس طرح قبیلہ جرہم کے لوگ
وادی بکہ میں آباد ہو گئے.اسمعیل ذبیح اللہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل کو وادی بلکہ میں آباد کرنے کے بعد حضرت ابراہیم
گا ہے گا ہے ملکہ آیا کرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے.جب حضرت اسمعیل
کی عمر کچھ بڑی ہوئی یعنی بعض روایات کی رُو سے وہ تیرہ سال کے ہو گئے تو حضرت ابرا ہیم“ نے ایک
خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسمعیل کو ذبح کر رہے ہیں.چونکہ ابھی تک حضرت ابرا ہیم" پر یہ تعلیم نازل نہیں
ہوئی تھی کہ انسانی قربانی ظاہری صورت میں جائز نہیں ہے اور ملک میں انسانی قربانی کا دستور تھا، اس لیے
حضرت ابراہیم نے اپنی اس خواب کو ظاہر میں پورا کرنا چاہا اور حضرت اسمعیل سے اس کا ذکر کیا.اسمعیل
نے کہا کہ آپ بے شک اپنی خواب کو پورا کریں، میں خدا کے حکم کی تعمیل کے لئے حاضر ہوں.چنانچہ
حضرت ابراہیم حضرت اسمعیل کو باہر لے گئے.اور اسمعیل کو زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو
گئے.اور وفادار بیٹے نے خاموشی اور خوشی کے ساتھ اپنی گردن باپ کے سامنے رکھ دی.قریب تھا کہ
بخاری کتاب بدء الخلق وسيرة ابن ہشام
پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۴ تا ۲۱
مسلم جلد ۲ باب و صیۃ النبی صلعم بابل مصر
Page 92
22
حضرت ابرا ہیم" چھری چلا دیتے ، مگر اُس وقت خدائی فرشتہ نے آواز دی کہ اے ابراہیم! تو نے اپنی
طرف سے اپنی خواب کو پورا کر دیا.اب اسمعیل کو چھوڑ اور اس کی جگہ ایک مینڈھا لے کر خُدا کے
راستے میں قربان کر دے کہ ظاہر میں یہی اس کی علامت ہے لیکن خواب کا جو حقیقی منشاء ہے وہ اور طرح پورا
ہوگا.چنانچہ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا اور اس کی یادگار میں مسلمانوں میں حج کے موقع پر قربانی کی
رسم قائم ہوئی.اس خواب کے حقیقی منشاء کے متعلق اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک صحیح معنے یہی ہیں کہ ذبح کرنے
سے خدا کے رستے میں وقف کرنا مراد ہے جو گویا دنیوی لحاظ سے زندگی کا خاتمہ کر دینے کے مترادف ہے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمعیل" کو مکہ میں آباد کرنے کی غرض وغایت ہی یہ تھی کہ کعبتہ اللہ کی تعمیر ہو
اور اس کی خدمت اور توحید کے قیام کے لئے حضرت اسمعیل کی زندگی وقف ہو جائے اور پھر جب مرور
زمانہ سے بُت پرستی نے توحید پر غلبہ پالیا تو اس مقدس خواب کی تعبیر میں خُدا نے حضرت اسمعیل کی نسل
میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے حلقہ بگوشوں کے ساتھ تو حید کی
اشاعت کے لئے اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں میں قربان کر دیا.اور یہی وہ ذبح عظیم یعنی عظیم الشان قربانی
ہے جس کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اسمعیل کی ظاہری قربانی کے بدلہ میں ایک
عظیم الشان قربانی کو مقرر کر دیا اور حج کے موقع پر جانور قربان کرنے کی رسم بھی مسلمانوں میں اسی مقدس
یاد کو تازہ رکھنے کے لئے ہے کہ انہیں خدا کے رستے میں قربان ہونے کے لئے ہر وقت تیار رہنا چاہئے.اس جگہ یہ ذکر
حضرت اسمعیل اور حضرت ہاجرہ کے متعلق بعض اعتراضات کا جواب ضروری ہے کہ
بعض عیسائی مؤرخین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت اسمعیل کے عرب میں آباد ہونے کا
کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے اور اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل اسمعیل میں سے ہونا بھی ان
کے نزدیک غیر مسلم ہے.نیز ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تھا وہ
جیسا کہ بائیبل میں بیان ہوا ہے حضرت اسحاق تھے.نہ کہ حضرت اسمعیل.ان ہر دو اعتراضات کا
جواب مختصر طور پر ذیل میں درج کیا جاتا ہے.پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ :
-- حضرت اسمعیل کا عرب میں آکر آباد ہونا اور قریش مکہ کا حضرت اسمعیل کی نسل میں سے
قرآن شریف سورة صافات ۱۰۲ تا ۱۰۵ و تفسیر ابن جریر شرح سورة مذکور : سورة صافات : ۱۰۸
-1
Page 93
ZA
ہونا عرب کی متحدہ روایات سے قطعی طور پر ثابت ہے اور عرب کی کوئی ایک روایت بھی اس
کے خلاف نہیں پائی جاتی.نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے اور نہ آپ کے
بعد ی اور چونکہ کسی قوم کی تاریخ کے متعلق سب سے مقدم شہادت اس کی اپنی صحیح روایات ہی
ہوتی ہیں.اس لیے مذکورہ بالا شہادت کے ہوتے ہوئے کوئی غیر متعصب شخص اس بات میں
شک نہیں کر سکتا کہ حضرت اسمعیل عرب میں آکر آباد ہوئے اور قریش کا قبیلہ آپ ہی کی
مبارک
نسل میں سے تھا.۲- قرآن شریف نے بھی جس کی تاریخی اسناد دوست و دشمن میں مسلم ہے قریش کونسل ابراہیم
میں شمار کیا ہے.-
-۵
خود بائیبل سے یہ ثابت ہے کہ حضرت سارہ کی ناراضگی کی وجہ سے حضرت اسمعیل اور
حضرت ہاجرہ وطن سے بے طن ہوئے.اب اگر حجاز وہ ملک نہیں جہاں وہ آ کر آباد ہوئے تو
پھر وہ جگہ کونسی ہے جہاں اُن کی نسل پائی جاتی ہے.بائیبل سے یہ ثابت ہے کہ حضرت اسمعیل اور اُن کی والدہ ایسی جگہ جا کر آباد ہوئے تھے جو
غیر آباد اور بیابان جگہ تھی.جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور نہ کوئی آبادی تھی ہے
اور یہ نقشہ مکہ کی واد غیر ذی زرع پوری پوری مطابقت رکھتا ہے.پھر بائیبل سے ہی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وطن سے نکلنے کے بعد حضرت ہاجرہ اور
حضرت اسمعیل فاران میں جا کر آباد ہوئے تھے.اور قطع نظر اس کے کہ فاران کے معنے ہی
ایک غیر آباد بنجر جگہ کے ہیں.عرب کے جغرافیہ دان اس بات پر متفق ہیں کہ فاران مکہ یا
حجاز کی پہاڑیوں کا نام ہے.اور جو لوگ عرب میں ہو آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ اور
مدینہ کے درمیان وادی فاطمہ میں جو بچے گل جذیمہ بیچتے نظر آتے ہیں، اُن سے اگر یہ پوچھا
جاوے کہ یہ پھول کہاں سے لائے گئے ہیں تو اُن کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مِنْ بَرِيَّةِ فَارَانَ
لے: دیکھو بخاری ومسلم وطبری وابن ہشام وابن سعد زرقانی وخمیس وغیرہ
قرآن شریف سورۃ حج آیت : ۷۹
۴ : پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۴ تا ۲۱
: فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۳۸
۳ : پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۴
۵ : پیدائش باب ۲۱ آیت ۲۱
ک : معجم البلدان جلد ۶ صفحه ۳۲۳
Page 94
۷۹
یعنی دشت فاران سے.اس شہادت کے ہوتے ہوئے اگر فاران کسی اور جگہ کا بھی نام ہے
تو بے شک ہو لیکن جب کہ حجاز میں بھی فاران کا ہونا ثابت ہے تو لا محالہ نسلِ اسمعیل سے تعلق
رکھنے والا فاران یہی حجاز والا فاران سمجھا جائے گا نہ کہ کوئی اور.- بائیبل میں یہ بھی مذکور ہے کہ وطن سے نکلنے کے بعد حضرت اسمعیل کی نسل ” حویلہ سے لے کر
شور تک، بستی تھی یے اور خود عیسائی محققین نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حویلیہ اور شور سے عرب کی مقابل
کی اطراف مراد ہیں..ے.بائیل میں حضرت اسمعیل کے متعلق وحشی یعنی جنگل میں رہنے والے کے الفاظ بھی آتے
ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بطور پیشگوئی کے مذکور ہے کہ اسمعیل کے مکہ میں آباد
ہونے کے ساتھ بالکل مطابقت کھاتی ہے.اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ خود لفظ عرب کے معنے
بھی جنگل اور ویران علاقہ کے ہیں.جیسا کہ اعراب کے لفظ سے ظاہر ہے جس کے معنے جنگل
-^
کے رہنے والوں کے ہیں ہے
مسیحیوں کے مشہور امام پولوس یعنی سینٹ پال نے اس بات
کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت اسمعیل
کی والدہ حضرت ہاجرہ کو عرب سے نسبت ہے.- قیدار جو مسلمہ طور پر حضرت اسمعیل کی اولاد سے تھا.اس کے متعلق بائیبل سے یہ بات
ثابت ہے کہ اس کی نسل عرب میں آباد تھی.،،
۱۰ اسی قیدار بن اسمعیل کے متعلق انسائیکلو پیڈیا میں یہ الفاظ درج ہیں کہ وہ اسمعیل کا بیٹا تھا،
جس کی نسل عرب کے جنوبی حصہ میں آباد ہوئی.“
مندرجہ بالا دلائل سے یہ بات روزِ روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت اسمعیل عرب میں آباد
ہوئے اور عرب کی آبادی کا ایک حصہ انہی کی نسل سے ہے اور جب یہ ثابت ہے تو عرب کی ان زبر دست
لی : پیدائش باب ۲۵ آیت ۱۸
: انسائیکلو پیڈیا بلی کا مطبوعہ لنڈن ۱۸۶۴ء بحوالہ ریویو آف ریلیجنز جلد۳۳
۳ : پیدائش باب ۱۶ آیت ۱۲
: تاج واقرب الموارد و غیره
ه : گلتیوں باب ۴ آیت ۲۲ تا ۲۵ یسعیاہ باب ۲۱ آیت ۱۳ تا ۱۸
ی انسائیکلو پیڈیا بلی کا مطبوعہ لنڈن ۱۸۶۲ ء بحوالہ ریویو آف ریجنز جلد ۳۳
Page 95
۸۰
روایات کو جن سے قریش کا حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے ہونا ظاہر ہوتا ہے رڈ کرنا ہرگز انصاف پر مبنی
نہیں سمجھا جا سکتا.دوسرا سوال یہ ہے کہ ذبیح کون تھا ؟ یعنی حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں سے کس کو خُدا کی راہ
میں قربان کر دینے کا تہیہ کیا تھا.سو اس کے متعلق پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہئے کہ یہ سوال کوئی خاص
اہمیت نہیں رکھتا.کیونکہ خواہ حضرت اسمعیل ذبیح ثابت ہوں یا اسحاق“ اس کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے دعاوی پر یا اسلام کے کسی بنیادی اصول پر اثر نہیں پڑتا، مگر ایک تاریخی واقعہ کے لحاظ سے یہ بات ضرور
قابل تحقیق ہے کہ ذبیح کون ہے؟ سوجیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے ہماری رائے میں درست بات یہی
ہے کہ ذیح حضرت اسمعیل تھے نہ کہ حضرت اسحاق.بے شک بائیبل میں حضرت اسحاق کو ذبیح بیان کیا گیا
ہے مگر اول تو بائیبل کی تاریخی حیثیت زیادہ مضبوط نہیں ہے.دوسرے خود بائیبل ہی کے بیان سے یہ دعویٰ
غلط ثابت ہوتا ہے اور اسلامی روایات کی شہادت مزید برآں ہے.بہر حال اس مسئلہ میں ہمارے دلائل کا
خلاصہ یہ ہے:
1- قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم نے ہم سے نیک اور صالح اولاد کی دُعا کی اور ہم نے
اُسے ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی.اور جب وہ لڑکا کچھ بڑا ہوا تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ
اپنے اس بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں.اس پر ابراہیم اپنے اس بیٹے کو خدا کی راہ میں جسمانی طور پر قربان کر
دینے کے لئے تیار ہو گئے اور بیٹے نے بھی خدائی حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن عین اس وقت جب
کہ ابراہیمؑ اپنے بیٹے کو گرا کر اس کے گلے پر چھری پھیر نے لگے خدائی فرشتہ نے انہیں اس فعل سے روک
دیا..الخ.اور پھر اس کے بعد آگے چل کر آتا ہے کہ ہم نے
ابراہیم کو الحق کی بشارت دی.اس بیان سے
یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ جس بیٹے کے ذبح کرنے کے لئے حضرت ابرا ہیم تیار ہوئے تھے وہ
اسمعیل تھے نہ کہ اسحق.کیونکہ قرآن شریف نے حضرت ابرا ہیم کے بڑے بیٹے کا ذکر کر کے اُس کے ساتھ
ذبح کے واقعہ کو جوڑا ہے اور الحق کی پیدائش کا اس کے بعد ذکر کیا ہے؛ حالانکہ اگر حضرت الحق ذبیح ہوتے تو
ذبیح کا ذکر اسحق کے ساتھ ملا کر ہونا چاہئے تھا نہ کہ حضرت ابرا ہیم کے بڑے بیٹے کے ساتھ.-۲- قرآن شریف میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ خُدا نے جب حضرت ابراہیم کو حضرت اسحق کی بشارت دی تو
اس کے ساتھ ہی اسحاق کے بیٹے یعقوب کی بھی بشارت دی یعنی ایک ہی وقت میں بیٹے اور پوتے دونوں
: سورة صافات آیت ۱۱۳
Page 96
ΔΙ
کی بشارت دی گئی.اب جب شروع سے ہی حضرت الحق کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب کی بشارت بھی
موجود تھی تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم اسحاق کو جسمانی طور پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو
جاتے جب کہ وہ جانتے تھے کہ اس کی زندگی کم از کم اس وقت تک مقدر ہے کہ اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہو.۳.حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اَنَا ابْنُ النَّبِيُحَيْنِ یعنی میں دو
ذبیحوں
کا بیٹا ہوں کا یعنی ایک حضرت اسمعیل اور دوسرے عبد اللہ بن عبدالمطلب جنہیں آپ کے دادا نے
ایک نذر کے نتیجہ میں قربان کرنا چاہا تھا اور وہ اس کے لئے تیار ہو گئے تھے.اس حدیث سے کم از کم اس
قدرضرور ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محقق بات یہی تھی کہ ذیح حضرت اسمعیل
تھے نہ کہ حضرت اسحاق.۴ - بائیبل سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں یہ طریق رائج تھا کہ سب سے بڑا بچہ خدا کے لئے
وقف کر دیا جاتا تھا.اور چونکہ وقف بھی رُوحانی رنگ میں ذبح کا ہم معنے ہے، اس لئے حضرت ابرا ہیم
کی نسل میں اس رسم کے پائے جانے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ذبیح حضرت اسمعیل تھے، کیونکہ وہ
حضرت ابراہیم کے بڑے لڑکے تھے اور اسحق چھوٹے.۵- ذبح کے متعلق قومی رنگ میں جتنی بھی رسوم تھیں وہ سب عربوں میں پائی جاتی تھیں اور اب بھی پائی
جاتی ہیں اور اُن میں سے کوئی بھی بنو اسرائیل میں نہیں پائی جاتی جو اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ ذبیح
حضرت اسمعیل تھے نہ کہ حضرت اسحق.کیونکہ اگر ذبیح حضرت اسحق ہوتے تو یہ رسوم بنو اسمعیل کی بجائے
بنواسرائیل میں پائی جانی چاہئے تھیں ، مگر معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے.مثلاً بائیل سے معلوم ہوتا ہے کہ
وہ لوگ جن کی زندگی خدا کے لئے وقف ہو جو ذبح کا حقیقی مفہوم ہے وہ بال منڈوانے سے باز رہتے تھے.مگر با وجود اس کے کہ بائیبل حضرت اسحق کے ذبیح ہونے کی مدعی ہے بنواسرائیل میں ایسی کوئی رسم نہیں
پائی جاتی جو اس قربانی کی یاد گار سمجھی جاسکے.لیکن اس کے بالمقابل عربوں میں جونسل اسمعیل میں سے
ہونے کے دعویدار ہیں یہ رسم اسلام سے پہلے بھی پائی جاتی تھی اور اسلام کے بعد بھی جاری رہی.چنانچہ حج
کے موقع پر قربانی سے پہلے عربوں میں بال منڈانے یا کترانے سے باز رہنے کا دستور تھا جو اسلام میں بھی
قائم رہا.اسی طرح عربوں میں حج کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا دستور تھا، جو اس مینڈھے کی قربانی کی
: سورۃ ہود آیت: ۷۲
: خمیس جلد اصفحه ۱۰۸
سے : گنتی باب ۸ آیت ۱۷ واستثناء باب ۲۱ آیت ۱۵ تا ۱۷ : قاضیوں باب ۱۳ آیت ۴
Page 97
۸۲
یاد گار تھا جو حضرت اسمعیل کے بدلے میں قربان کیا گیا.اور یہ دستور اسلام میں بھی قائم رہا.مگر بنواسرائیل
میں یہ رسم کہیں نظر نہیں آتی.ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ قربانی کا ورثہ حضرت اسمعیل کی اولاد نے پایا ہے
نہ کہ حضرت الحق کی اولاد نے.اور ظاہر ہے کہ جس قوم نے یہ ورثہ پایا ہے اُسی کا جد اعلیٰ ذبیح سمجھا
جانا چاہئے.-4
"
بائیل میں مقام ذبح یعنی قربان گاہ موریا کو ظاہر کیا گیا ہے، مگر یہ تصریح نہیں ہے کہ یہ جگہ کہاں
واقع ہے.البتہ یہ ذکر ہے کہ یہ ایک پہاڑی جگہ ہے.بائیبل میں اس جگہ کے متعلق تصریح نہ ہونے کی وجہ
سے خود یہودی اور مسیحی علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ جگہ کہاں اور کونسی ہے ، لیکن غور کریں تو مکہ کے
پاس کی پہاڑی ”مروہ کے ساتھ یہ نام اور یہ تشریح بالکل منطبق ہو جاتی ہے.اور نام میں جو خفیف سا فرق
ہے وہ زبانوں کے اختلاف کی بنا پر قابل لحاظ نہیں ہے.بے شک یہ درست ہے کہ اب حج کے موقع پر قربانی
مروہ کے پاس نہیں ہوتی بلکہ منی میں ہوتی ہے لیکن اول تو منیٰ اور مروہ ایک دوسرے کے پاس ہی ہیں.دوسرے حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل قربان گاہ
مروہ ہی تھی ہے مگر بعد میں حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے آبادی سے فاصلہ پر مقرر کر دی گئی.ے.بائیبل نے باوجود اس کے کہ ذیح حضرت اسحق کو بیان کیا ہے اس واقعہ کی تفصیل میں ایسی باتیں درج
کی ہیں کہ وہ حضرت اسحق پر نہیں بلکہ حضرت اسماعیل پر صادق آتی ہیں.قربانی کا ذکر بائیبل میں کتاب
پیدائش " میں کیا گیا ہے ، مگر اس بیان میں جہاں الحق کو ذبیح کہا گیا ہے وہاں ساتھ ہی انہیں حضرت ابرا ہیم
کا اکلوتا بیٹا کہ کر پکارا گیا ہے؛ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ حضرت اسحق کسی صورت میں بھی حضرت ابراہیم کے
اکلوتے بیٹے نہیں کہلا سکتے بلکہ اکلوتا کہلانے کا حق اگر کسی کے لئے سمجھا جاسکتا ہے تو وہ حضرت اسمعیل ہیں.کیونکہ حضرت اسمعیل تیرہ چودہ سال کی عمر تک حقیقۂ حضرت ابراہیم کے اکلوتے بیٹے تھے.مگر حضرت الحق
کو کبھی بھی یہ پوزیشن حاصل نہیں ہوئی.جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ابتداء بائیل میں بھی اسمعیل کو ہی
ذبیح بیان کیا گیا تھا مگر بعد میں قومی رقابت کے جذبات سے متاثر ہوکر یہودی علماء نے اس نام کو بدل کر
اسحاق کر دیا مگر تفصیلات میں بعض ایسی باتیں باقی رہ گئیں جو اس تحریف کو بے نقاب کر رہی ہیں.اسی طرح
بائیبل کے اس بیان میں یہ مذکور ہے کہ بیٹے کے ذبح سے روک دینے کے بعد خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم
سے فرمایا کہ تو نے میرے رستے میں قربانی کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا دریغ نہ رکھا اب میں تیری اولاد میں بہت
ل : پیدائش باب ۲۲ آیت ۲
: موطا امام مالک
: پیدائش باب ۲۲
Page 98
۸۳
برکت دُوں گا اور تیری نسل سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی.‘ ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ ذبیح وہ
لڑکا ہے جس کی نسل میں وہ عظیم الشان نبی پیدا کیا جانا مقدر تھا جو بلا امتیاز قوم وملت ساری دُنیا کے لیے
مبعوث ہونے والا تھا.اور ظاہر ہے کہ یہ وعدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر پورا ہوا، کیونکہ آپ ہی
وہ نبی ہیں جو ساری دُنیا کے لئے مبعوث ہوئے.چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے نبی صرف خاص
خاص قوموں کی طرف آتے تھے مگر میں سب اقوامِ عالم کی طرف بھیجا گیا ہوں.اس کے مقابل پر بنی
اسرائیل کے آخری نبی یعنی حضرت مسیح ناصری کے یہ الفاظ خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں کہ ”میں بنی اسرائیل
کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا.اور یہ کہ میں بچوں (یعنی بنی اسرائیل)
کی روٹی کتوں ( یعنی غیر قوموں) کے آگے نہیں ڈال سکتا.اسرائیلی نبیوں کی یہ محدود رسالت اور اس
کے مقابل پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر دعوت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ساری قوموں کو برکت
دینے کا وعدہ جو بیٹے کے ذبح کے انعام میں حضرت ابراہیم سے کیا گیا وہ حضرت اسحق کی اولاد میں نہیں بلکہ
حضرت اسمعیل کی اولاد میں پورا ہوا.اور یہ کہ ذیج حضرت اسمعیل تھے نہ کہ اسحق.اس بحث کے ختم کرنے سے قبل ایک اور اعتراض کا جواب دینا بھی ضروری ہے جو بعض متعصب
مسیحیوں کی طرف سے حضرت ہاجرہ کے متعلق کیا جاتا ہے اور وہ یہ کہ حضرت ہاجرہ محض ایک لونڈی تھیں اور
حضرت ابرا ہیم کی اصل بیوی حضرت سارہ تھیں اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی کی اولاد سے
ہیں.اس اعتراض کے متعلق پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہئے کہ یہ اعتراض محض حسد اور عداوت کی وجہ سے
پیدا ہوا ہے ورنہ ایک ہی منہ سے ایک ہی وقت میں یہ دو اعتراض نہیں نکل سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نسل اسمعیل میں سے نہیں ہیں اور یہ کہ آپ ایک لونڈی کی نسل سے ہیں.کیونکہ یہ دونوں باتیں ایک
دوسرے کے متضاد ہیں.لیکن چونکہ غرض یہ ہے کہ اگر ایک اعتراض نشانہ پر نہ بیٹھے، تو دوسرا اس کی جگہ لینے
کے لئے تیار ہو.اس لیے ایک ہی سانس سے یہ گرم وسرد ہوا نکالی جارہی ہے.لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر
دواعتراض غلط اور غیر موثر ہیں.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل اسمعیل میں سے ہونے کی بحث
تو او پر گذر چکی ہے اور حضرت ہاجرہ کے متعلق اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اول تو کسی یقینی دلیل سے ان کا
لونڈی ہونا ثابت نہیں ہوتا.عربی نسخوں میں ان کے متعلق عموماً جاریہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنے
ا : بخاری کتاب الصلوۃ باب جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً
۲ : متنی باب ۱۵ آیت ۲۴
: مرقس باب ۷ آیت ۲۷
Page 99
۸۴
لونڈی اور لڑکی ہر دو کے ہیں.لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت ہاجرہ کبھی غلامی کی قید میں رہی تھیں تو
پھر بھی اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جب حضرت ابراہیم نے انہیں اپنے عقد میں لے لیا تو انہیں
بیوی کے طور رکھا تھا نہ کہ لونڈی کے طور پر.اور اگر محض ایک عرصہ کے لیے قید غلامی میں رہنا قابلِ
اعتراض ہے تو ہمارے معترضین کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس داغ سے حضرت سارہ بھی محفوظ نہیں رہیں.کیونکہ یہ ثابت ہے کہ جب حضرت ابرا ہیم مصر میں تشریف لے گئے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو
حضرت ابراہیم سے چھین کر اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا اور پھر انہیں کچھ عرصہ کے بعد رہائی نصیب ہوئی
تھی.یہ اور بنو اسرائیل کے جد امجد حضرت یوسف بن یعقوب کا مصر میں غلام بن کر فروخت ہونا اور ایک
عرصہ دراز تک اسی حالت میں زندگی گزارنا تو ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے سکولوں کے کم سن بچے بھی
واقف ہیں.پس اگر حضرت ہاجرہ کی زندگی کا کوئی حصہ قید غلامی میں بسر بھی ہوا تو یہ کوئی طعن کی بات نہیں
ہے.لیکن حق یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کا لونڈی ہونا ہی غیر ثابت ہے بلکہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف
اس قدر ہے کہ جب مصر کا بادشاہ اپنے فعل شنیع کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ سے مرعوب
ہوا تو اس نے نہ صرف حضرت سارہ کو آزاد کر دیا بلکہ اپنے حرم سے ایک شریف اور ہونہار لڑکی بھی حضرت
سارہ اور حضرت ابراہیم کے پیش کی اور وہ لڑکی یہی حضرت ہاجرہ ہیں.بائیبل اور اسلامی روایات ہر دو میں
جس طرح شاہ مصر کا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ سے مرعوب ہونا اور اُن کی بزرگی اور قوتِ رُوحانی کا
قائل ہونا بیان ہوا ہے، اس سے یہ ہرگز بعید از قیاس نہیں کہ ہاجرہ خودشاہ مصر کے قریبی عزیزوں میں سے
ایک لڑکی ہوں جو اُس نے اپنے اس فعل کی تلافی میں جو حضرت سارہ کے بارے میں اُس سے سرزد ہوا
حضرت ابراہیم اور سارہ کی خدمت میں پیش کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ بعد میں لونڈی قرار دے دی گئی.یہ صرف قیاس ہی نہیں ہے بلکہ بعض پرانے محققین نے اسے بطور ایک حقیقت کے بیان کیا ہے.چنانچہ ایک
یہودی عالم جس کا نام دبشلوم ہے اپنی تو رات کی تفسیر میں یہاں تک لکھتا ہے کہ ہاجرہ خودشاہ مصر کی اپنی
لڑکی تھی جو اس نے سارہ کی کرامت دیکھ کر اس کی خدمت کے لیے پیش کر دی تھی.الغرض لونڈی ہونے کا الزام بالکل غلط اور نا درست ہے، لیکن اگر بالفرض غلامی ثابت بھی ہو تو یقیناً
ایسی غلامی کسی داغ کا باعث نہیں ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو جبراً اس کی آزادی سے محروم کر کے قید میں
پیدائش باب ۲ ایت ۱۴ تا ۲۰ نیز چیمبرس انسائیکلو پیڈیا ایڈیشن ۱۹۳۰ء جلد اصفحہ ۱۸ کالم۲
: ارض القرآن جلد ۲ صفحه ۴۱
Page 100
۸۵
ڈال لیا جائے جیسا کہ عموماً اس زمانہ میں ہوتا تھا.اگر یہی غلامی ہے تو دُنیا کی کوئی شریف اور آزاد قوم بھی
اس غلامی کے داغ سے محفوظ نظر نہیں آتی.خود بنی اسرائیل کی قوم ایک بڑے لمبے عرصہ تک یعنی ابتداء مصر
میں اور پھر بابل میں غلامی کی قید میں محبوس رہی ہے.مگر یقیناً اس وجہ سے بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ
غلام زادے نہیں کہلا سکتے اور نہ ہی حضرت سارہ کا شاہ مصر کے حرم میں عارضی طور پر محبوس رہنا یا حضرت
یوسف کا عزیز مصر کے گھر میں بطور غلام کے زندگی بسر کرنا کسی اسرائیلی فرزند کے لیے باعث طعن سمجھا
جاسکتا ہے.فافهم
تعمیر کعبہ
اس ضمنی مگر ضروری بحث کے بعد ہم اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں.یہ بتایا جا چکا ہے
کہ حضرت ابرا ہیم نے خدائی حکم کے ماتحت حضرت ہاجرہ اور اُن کے فرزند دلبند کو مکہ کی
وادی غیر ذی زرع میں لاکر آباد کیا.اور پھر واپس تشریف لے گئے.جب حضرت ابراہیم عرب میں
دوبارہ سہ بارہ تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ فوت ہو چکی تھیں.اور اتفاق سے دونوں دفعہ حضرت اسمعیل
بھی کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور اس وجہ سے باپ بیٹے کی ملاقات نہیں ہوسکی.اس پر حضرت ابراہیم چوتھی
دفعہ پھر عرب میں تشریف لائے اور اس دفعہ دونوں نے مل کر مکہ میں ایک عبادت خانہ کی تعمیر شروع کی.یہ
عبادت خانہ دراصل بہت پرانا تھا.مگر اس کے نشان مٹ چکے تھے.اور حضرت ابراہیم نے خُدا سے علم
پا کر اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کی تجویز کی تھی.حضرت اسمعیل تعمیر کے کام میں آپ کے مددگار تھے
اور آپ کو پتھر لا لا کر دیتے تھے.جب دیوار میں کچھ اونچی ہو گئیں تو حضرت ابرا ہیم نے ایک خاص پتھر
لے کر کعبہ کے ایک کو نہ میں نصب کیا تا کہ وہ لوگوں کے لئے بطور نشان کے ہو کہ بیت اللہ کا طواف
یہاں سے شروع کرنا چاہئے.یہ حجر اسود ہے جسے حج میں طواف کے وقت منہ سے یا ہاتھ کے اشارہ
سے بوسہ دیتے ہیں.مگر یا درکھنا چاہیے کہ حجر اسود کوئی بالذات مقدس چیز نہیں ہے اور نہ ہی طواف کے
وقت اسے بوسہ دینا کسی طرح شرک سمجھا جاسکتا ہے بلکہ وہ محض علامت کے طور پر ہے اور اصل نقدس
صرف ان پاک روایات کو حاصل ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ وابستہ ہیں.چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ
ایک دفعہ جب حضرت عمر خلیفہ ثانی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے ، تو آپ نے حجر اسود کی طرف منہ کر کے
فرمایا کہ اے پتھر ! میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے اور تجھے نفع یا نقصان کی کوئی طاقت حاصل
نہیں ہے.اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز بوسہ
1 : بائیبل وانسائیکلو پیڈیا
: از رقی وزرقانی و خمیس
: خمیس
Page 101
۸۶
نہ دیتا.علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ طواف میں صرف حجر اسود والے کونے کو ہی بوسہ نہیں دیا جاتا
بلکہ اس کے ساتھ والے دوسرے کونے کو بھی بوسہ دیا جاتا ہے اور باقی دوکونوں کو بوسہ دینا اس لیے ترک کیا
جاتا ہے کہ بوجہ حطیم کی جگہ چھوٹ جانے کے وہ اپنی اصلی جگہ پر قائم نہیں رہے.اس طرح بھی حجر اسود کی
کوئی خصوصیت نہیں رہتی ہے غرض حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل نے مل کر ان گھڑت پتھروں کا ایک
بے چھت چوکور کوٹھا تیار کیا جس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور طول ۳۲ ہاتھ تھا اور عرض ۲۲ ہاتھ یا یہی خانہ کعبہ
ہے جو آج مربع خلائق ہے.دُعائے خلیل قرآن شریف میں اس تعمیر کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے :
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبُرَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمُعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُسْلِمَةٌ لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ) رَبَّنَا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكتب
وو
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ :
بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے فائدہ کی غرض سے خدا کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ
وہی ہے جو وادی بکہ میں ہے جو برکت دیا گیا ہے اور ہدایت کا باعث بننے والا ہے سارے
جہان کے لئے.اور یا دکر و جب ابراہیم اور اسمعیل اس گھر کی بنیاد میں اُٹھا رہے تھے اُس وقت
وہ اللہ سے دُعائیں کرتے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول کر.بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے.اور اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنے
فرمانبردار بندے بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرمانبردار جماعت پیدا کر اور ہم کو
عبادت اور حج کے طریقے بتا اور ہماری طرف رجوع برحمت ہو.بے شک تو رحمت کے ساتھ
رجوع کرنے والا اور بہت مہربان ہے.اے ہمارے رب تو مبعوث کیجیوان میں اپنا ایک
رسول انہی میں سے جو تیری آیات اُن کو سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو
: بخاری کتاب الحج : تاریخ مکه از رقی
ل : بخاری کتاب وجوب الحج
: سورۃ آل عمران : ۹۷
۵: سورة بقره آیت ۱۲۸ تا ۱۳۰
Page 102
۸۷
پاک وصاف کرے.بے شک تو غالب اور حکیم.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی دردمندانہ دعا کا نتیجہ تھی ؛ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ
اَنَا دَعْوَةُ إِبْرَا هِیمَ یعنی میں ابراہیم کی دُعا کا ثمرہ ہوں یا
اعلان حج جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو ذات باری تعالی کی طرف سے حضرت ابرا ہیم کو ارشاد
ہوا:
وَطَهَرُ بَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَالْقَابِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَاذِنْ فِي النَّاسِ
بِالْحَقِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلَى كُلِ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور
سجدہ کرنے والوں کے واسطے پاک وصاف رکھ.اور اعلان کر لوگوں میں کہ وہ اس کے حج کے
لیے آئیں.وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل چل کر اور ڈبلی ڈبلی یعنی لمبے لمبے سفر کرنے والی
اونٹنیوں پر سوار ہوکر جو ہر دور دراز رستے سے آئیں گی.یہ اعلان کعبتہ اللہ کے مرکز بننے کی بنیاد ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جلدی ہی کعبہ تمام عرب کا
مذہبی مرکز بن گیا اور عرب کے دُور دراز حصوں سے اُس کے حج کے لیے لوگ آنے لگے.تولیت کعبہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ مکہ میں سب سے پہلے آباد ہونے
والا قبیلہ جرہم الثانیہ تھا.ان
کے
رئیس مضاض بن عمرو کی لڑکی سے حضرت اسمعیل" کی شادی ہوئی جس سے بارہ بچے پیدا
ہوئے.جن میں سے بڑے کا نام نابت اور اُس سے چھوٹے کا نام قیدار تھا.اہلِ عرب زیادہ تر قیدار بن
اسمعیل کی اولاد ہیں اور قریش بھی قیدار کی نسل سے ہیں.جب تک حضرت اسمعیل زندہ رہے ، وہ خود کعبہ
کے متولی تھے لیکن ان کی وفات کے بعد اُن کے بڑے صاحبزادے نابت متوتی ہوئے.جب یہ بھی
وفات پاگئے تو کعبہ کی تولیت نابت کے نانا مضاض بن عمرو کے پاس آ گئی اور پھر ایک بڑے لمبے عرصہ تک
قبیلہ جرھم ہی کے پاس رہی.مگر ایک طویل زمانہ کے بعد بنو قحطان کی ایک شاخ قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ جرھم
پر غلبہ پالیا اور کعبہ کی تولیت اُن سے چھین لی.قبیلہ جرھم کو مکہ سے نکالے جانے کا سخت صدمہ ہوا اور وہ یہاں سے نکل کر پھر یمن کی طرف ہجرت کر
گئے لیکن مکہ سے نکلنے سے پہلے اُن کے رئیس عمرو بن الحرث نے اپنے قومی اموال کو چاہ زمزم میں ڈال کر
ل : ابن عساکر بحوالہ جامع الصغیر : سورۃ حج آیت ۲۷ ، ۲۸
Page 103
۸۸
اُسے اُوپر سے بند کر دیا اور اس طرح جب قبیلہ خزاعہ کے لوگ مکہ میں داخل ہوئے تو یہ مقدس چشمہ غائب
تھا اور پھر یہ سینکڑوں سال تک بندر ہاحتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے اس کا
نشان پتہ لگا کر اسے پھر جاری کیا.بہر حال قبیلہ جرہم کے بعد قبیلہ خزاعہ ملکہ کا حاکم اور کعبہ کا متولی ہوائے
کعبہ میں بت پرستی کی آمد اسی قبیلہ خزاعہ کے رئیس عمرو بن لھی کی طرف منسوب کی جاتی ہے.یہ جسے شام میں
بت پرستوں کو بت پوجتے دیکھ کر یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کعبہ میں بھی ایسے بُت ہوں اور لوگ انہیں
پوجیں.چنانچہ اس نے چند بُت شام سے لا کر کعبہ کے آس پاس قائم کئے..چونکہ اس وقت کعبہ عرب کا
مذہبی مرکز بن چکا تھا اور لوگ ہر سال یہاں حج کے واسطے جمع ہوتے تھے اس لیے اس ذریعہ سے تمام ملک
میں بت پرستی پھیل گئی.اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے عرب کے کسی حصہ میں بُت پرستی نہ تھی بلکہ
صرف یہ مقصد ہے کہ کعبہ میں بتوں کی آمد عرب کے ہر حصہ میں بُت پرستی کے پھیل جانے اور مستحکم ہو
جانے کا بڑا باعث ہوئی ؛ چنانچہ اس کے بعد آہستہ آہستہ صرف کعبہ میں بتوں کی تعداد ۳۶۰ تک پہنچ گئی.ایک بڑے عرصہ کے بعد کعبہ کی تولیت قبیلہ خزاعہ کے ہاتھ سے بھی نکل گئی.اس کی وجہ لکھتے ہوئے مؤرخین
ایک عجیب قصہ بیان کرتے ہیں جس کا یہاں درج کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا.فہر بن مالک کی اولاد یعنی قبیلہ قریش میں پانچویں صدی عیسوی کے نصف کے قریب ایک شخص گذرا
ہے جس کا نام قصی بن کلاب تھا.یہ بہت سمجھدار شخص تھا اور نو جوانی کے ایام میں ہی اس کے دل میں یہ
خواہش پیدا ہوگئی تھی کہ مکہ کی حکومت اور کعبہ کی تولیت اسماعیل کی اولا د کا ورثہ ہے جو کسی اور قوم کے ہاتھ
میں نہیں رہنا چاہیے.چنانچہ وہ مکہ آیا اور آہستہ آہستہ رسوخ پیدا کر کے حلیل بن حبشیہ خزاعی کی لڑکی حبیبی
سے شادی کر لی جو اس زمانہ میں قبیلہ خزاعہ کا رئیس تھا اور اس وقت اُسی کے ہاتھ میں کعبہ کی تولیت تھی.حلیل جب مرنے لگا تو اس نے یہ وصیت کی کہ میرے بعد کعبہ کی تولیت میری لڑکی حبسی زوجہ قصی کے سپرد
ہو.اس طرح کعبہ کی تولیت عملا قصی کے ہاتھ میں آ گئی.مگر قصتی کا دل صرف ایک مختار کی حیثیت پر تسکی
نہیں پاسکتا تھا بلکہ وہ ایک اصل حقدار کے طور پر ملکہ کا حاکم اور کعبہ کا متولی بننا چاہتا تھا.چنانچہ اس نے
آہستہ آہستہ اپنا حق جمانا شروع کیا.جب قبیلہ خزاعہ کے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت برہم ہوئے اور
لڑائی پر آمادہ ہو گئے.اُدھر قصی نے بھی اپنی قوم کے لوگ جمع کر لیے اور دونوں قبیلوں کے درمیان سخت
جنگ ہوئی.آخر اس بات پر صلح ہوئی کہ کسی شخص کو ثالث مقرر کیا جاوے.جو فیصلہ یہ ثالث کرے اُسے
ل : ابن ہشام
: بخاری باب قضہ خزاعه
: ابن ہشام
Page 104
۸۹
فریقین قبول کر لیں.چنانچہ ایک شخص عمرو بن عوف ثالث مقرر ہوا جس نے یہ فیصلہ دیا کہ کعبہ کی تولیت کا
اصل حقدار قصی ہے اور یہ کہ جتنے آدمی قبیلہ خزاعہ کے مارے گئے ہیں ان
کا کوئی فید یہ نہیں لیکن قصتی کے تمام
مقتولوں کا فدیہ قبیلہ خزاعہ ادا کرے.اس طرح ایک بڑے لمبے عرصہ کے بعد کعبہ کی تولیت پھر
بنو اسمعیل میں آگئی یا اور چونکہ کعبہ کی تولیت دنیوی جاہ و اقتدار کا ذریعہ بھی تھی کیونکہ وہ قبیلہ جس کے
ہاتھ میں یہ تولیت ہوتی تھی تمام عرب میں خاص عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے قریش
اس ذریعہ سے بہت معز ز مکرم ہو گئے.کعبہ کی دوبارہ سہ بارہ تعمیر ہر دنیوی چیز کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ لگا ہوا ہے؛ چنا نچہ کعبہ بھی
حضرت ابراہیم کی تعمیر کے بعد کئی دفعہ گرا اور کئی دفعہ بنا.بعض
اوقات کسی سیلاب کے زور سے جو مکہ کی وادی میں کبھی کبھی آجاتا تھا اس کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا تھا
اور اس کے متولی اسے گرا کر پھر تعمیر کرتے تھے اور بعض اوقات آگ یا کسی اور حادثہ کے نتیجہ میں ایسا کرنا
پڑتا تھا.چنانچہ ہر اس قوم کو کعبہ کی تعمیر کرنی پڑی جس کے ہاتھ میں اس کی تولیت گئی.بنو جرھم، خزاعہ اور
قریش سبھی نے اپنے اپنے وقت میں اس کی تعمیر کی.قصی نے بھی ایک دفعہ اس کی تعمیر کی اور پھر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور انہوں نے اس کے اندر کچھ ترمیمات بھی
کیں.چنانچہ انہوں نے اس کی بلندی کو زیادہ کر کے اُس کے اُوپر چھت ڈالی اور اس کے اندر چھ ستون بنائے
اور چھت میں ایک روشندان بنایا اور کعبہ کے دروازے کو اونچا کر دیا.مگر چونکہ ان کے پاس سامان تھوڑا تھا
اس لیے وہ کعبہ کو اس کی اصل ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے ایک طرف کو قریباً سات
ہاتھ جگہ چھوڑ دی.اس چھوڑے ہوئے حصہ کو حطیم یا حجر کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
کعبہ کا حصہ ہی قرار دیا ہے.چنانچہ طواف کے وقت اس حصہ کے باہر سے ہوکر گذرنا ضروری ہوتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عائشہ سے فرمایا کہ حطیم خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے اور قریش نے
اسے اس لیے باہر چھوڑ دیا تھا کہ ان کے پاس خرچ تھڑ گیا تھا اور انہوں نے کعبہ کے دروازے کو اس لیے
اونچا کر دیا تھا کہ تا وہ جسے چاہیں اندر آنے دیں اور جسے چاہیں روک دیں اور اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی
مسلمان نہ ہوئی ہوتی اور مجھے اُن کے تزلزل کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کی تعمیر کردہ عمارت کو گرا کر پھر اصل
ابراہیمی بنیادوں پر ساری عمارت کو تعمیر کرتا اور حطیم کو اس کے اندر شامل کر دیتا اور اس کے دروازہ کو نیچا کر
ل : ابن ہشام وطبری
Page 105
۹۰
دیتا اور اس کے موجودہ دروازے کے مقابل پر ایک اور درواز ہ بھی لگواتا “ چنانچہ ۲۴ ھ میں جب کسی وجہ
سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو عبد اللہ بن زبیر نے جو اس وقت مکہ کے حاکم تھے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا اور کعبہ کے اندر بجائے چھ ستونوں کے صرف تین ستون بنوائے ،لیکن
عبدالمالک بن مروان نے جب مکہ پر غلبہ پایا تو غالباً اس خیال سے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کام
کو نہیں کیا تو اور کسی کو بھی اس کا حق نہیں ہے، حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو
گرا کر پھر اسی رنگ میں عمارت بنوادی جاوے جس طرح وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی ؟
چنانچہ حجاج نے ایسا ہی کیا مگر تین ستونوں والی تبدیلی کو بحال رکھائے
كسوة كعبه شروع شروع میں کعبہ پر کوئی غلاف وغیرہ نہ ہوتا تھا، لیکن بعد میں یمن کے ایک بادشاہ
تبع اسد نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کو غلاف چڑھا رہا ہے چنانچہ اس نے
کعبہ پر غلاف چڑھوا دیا.اس کے بعد غلاف چڑھانے کی رسم جاری ہو گئی.چنانچہ قریش کعبہ پر ہمیشہ
غلاف چڑھایا کرتے تھے.اسلام میں بھی یہ رسم جاری رہی.چنانچہ آج تک کعبہ پر باقاعدہ ہر سال نیا
قیمتی غلاف چڑھایا جاتا ہے اور پرانا غلاف اتار کر حاجیوں میں تقسیم یا فروخت کر دیا جاتا ہے.آجکل جو
غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر جگہ جگہ کلمہ طیبہ اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوتی
ہیں.حُرمت کعبہ
زمانہ جاہلیت کے عربوں میں کعبہ کی عزت غالباً کچھ اس سے بھی زیادہ تھی جو مسلمانوں
کے دلوں میں ہے کیونکہ وہ کعبہ کو گویا ایک قسم کا معبود سمجھتے تھے اور اس پر چڑھاوے
چڑھاتے تھے.یہ چڑھاوے ایک زمین دوز خزانہ میں کعبہ اور اس کے پجاریوں اور حجاج کی ضرورت کے
واسطے محفوظ رکھے جاتے تھے.کعبہ خود تو حرم تھا ہی اس کے طفیل سے مکہ بلکہ مکہ کے آس پاس کا علاقہ بھی
حرم قرار دیا گیا تھا جہاں ہر قسم کا گشت و خون ممنوع تھا اَشْهُرِ حُرم کی خصوصیت بھی کعبہ ہی کی وجہ سے تھی
تا کہ حاجی لوگ امن کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے حج کے واسطے آ جاسکیں.یہ بھی دستور تھا کہ جس چیز
کی خاص طور پر حرمت ظاہر کرنی ہو وہ کعبہ پر آویزاں کر دی جاتی تھی.چنانچہ زمانہ جاہلیت کی سات مشہور
نظمیں کعبہ پر آویزاں کئے جانے کی وجہ سے ہی سبع معلقات کہلاتی ہیں.ل : بخاری کتاب الحج باب وجوب الحج وفضله از رقی وطبری و تاریخ کامل ابن اثیر و خمیس
: ازرقی
Page 106
۹۱
کعبہ کے ارد گرد مکانات کی تعمیر اس موقع پر یہ ذکر کردینا بھی مناسب ہوگا کہ قصی کے زمانہ تک
کسی قوم نے کعبہ کے پاس مکان نہیں بنائے تھے بلکہ اس سے
کچھ ہٹ کر عارضی گھروں اور خیموں میں رہتے تھے لیکن قمی تحریک سے قریش نے کعبہ کے چاروں طرف
مکانات تیار کر لیے اور مکہ گویا با قاعدہ شہر ہو گیا.لیکن یہ مکانات کعبہ کے ساتھ ملحق نہ تھے بلکہ حاجیوں کے
طواف کے واسطے کعبہ کے چاروں طرف کافی جگہ درمیان میں چھوڑ دی گئی تھی.یہ جگہ گویا مسجد حرام کا صحن
تھا.خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس جگہ کی تنگی محسوس کی گئی اور اردگرد کے مکانات گرا کر مسجد حرام کا
صحن وسیع کر دیا گیا.کعبہ اور مسجد حرام کا نقشہ جس حالت میں کہ وہ اب ہے یہ ہے:
(دیکھئے اگلے صفحہ پر )
Page 107
تاريخ السعر
يوف الفقرة
۹۲
نقشہ کعبہ و مسجد حرام
مساکن مک
بات الناسطية
اسب الأنانية
هروباً لفاض
رسم الحمد المكي
والطريق بين الصفا
والمروة والابواب
ان القطى
المنكية المضرته
اس نقشہ میں کعبہ کے ارد گرد جو سفید جگہ دکھائی گئی ہے وہ مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ ہے.اس
کے اردگرد جو سیاہ خطوط ہیں وہ نماز ادا کرنے کی جگہ ہے.اس کے ساتھ ملحق چاروں طرف کھلا میدان ہے
جس میں کہیں کہیں سیاہ خطوط میں رستے دکھائے گئے ہیں.اس میدان کے ارد گرد قبتے یعنی مسجد کے احاطہ
کی مستقف عمارت ہے.
Page 108
۹۳
قریش
قریش اس قبیلہ کا نام ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جو اس زمانہ میں
مکہ میں آباد تھا.یہ قبیلہ عرب کی متفقہ روایات کی رُو سے حضرت اسمعیل کی اولاد سے ہے اور
عدنانی قبائل کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے.قبیلہ قریش کے بانی کے متعلق روایات مختلف ہیں.بعض روایات میں نضر بن کنانہ کو اس کا بانی قرار
دیا گیا ہے اور بعض میں فہر بن مالک کو.مگر یہ اختلاف عملاً واقعات پر کوئی اثر نہیں ڈالتا کیونکہ نضر بن کنانہ
کے ہاں مالک بن نضر کے سوا کوئی لڑکا نہیں ہوا جس کی نسل چلی ہوا اور اسی طرح مالک کے ہاں سوائے فہر
کے کوئی لڑکا نہیں ہوا.گویا نضر کی اولاد بھی عملاً وہی ہے جو فہر کی ہے.قریش کی وجہ تسمیہ میں بھی اختلاف ہے.بعض کا یہ خیال ہے کہ اس قبیلہ کو قریش کا نام ایک مچھلی کی
مشابہت میں دیا گیا تھا جو بہت بڑی ہوتی ہے اور باقی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے اور جسے عربی زبان میں قریش
کہتے ہیں.گویا اس لفظ میں قریش کی طاقت اور اقتدار کی طرف اشارہ تھا، لیکن دوسرا گر وہ یہ کہتا ہے کہ
جب قصی نے کعبہ کی تولیت حاصل کرنے کے بعد اس قبیلہ کی مختلف شاخوں
کو جمع کر کے مکہ میں آباد کیا تو اس
وقت ان کا نام قریش ہوا.کیونکہ عربی زبان میں قریش کے روٹ میں جمع کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے.قبیلہ قریش کی اندرونی شاخیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریش کئی قبائل میں
تقسیم ہو چکے تھے جن کا بعض اوقات آپس میں فساد بھی ہو جاتا
تھا.گو با قاعدہ لڑائی کی نوبت کبھی نہیں پہنچی.ان قبائل میں سے بعض قبائل اور بعض مشہور افراد کا شجرہ درج ذیل ہے.اس شجرہ میں جن ناموں کے
ساتھ بنو کا لفظ لگایا گیا ہے وہ ایسے لوگوں کے نام ہیں جن کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
مشہور قبائل قریش خاص طور پر منسوب ہوتے تھے اور جن کے ساتھ یہ لفظ درج نہیں وہ صرف مشہور افراد ہیں.اور جو اسماء خطوط کے اندر درج ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مشہور لوگوں کے نام ہیں.ان
میں سے مسلمانوں کے نام گول دائرہ میں دکھائے گئے ہیں اور کفار کے نام چوکور خطوط میں.لیکن چونکہ اس شجرہ
میں سب نام نہیں دکھائے گئے اس لئے ایک ہی لائن میں درج شدہ ناموں کے متعلق یہ نہیں سمجھنا چاہئے
کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ ایک ہی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں.(دیکھئے اگلا صفحہ )
لے : زرقانی جلد اصفحہ ۷۶
: ابن سعد و سهیلی وزرقانی
Page 109
تیم الا درم
۹۴
عدنان
فهر بن مالک
محار
لوی
امیہ بن خلف أبي بن خلف عاص بن وائل
صفوان بن أمية
ابو عبيدة الجراح
بنو عدی
حضرت عمر بن الخطاب سعید بن زید
عمرو بن العاص
عبد اللہ بن عمر
حضرت ابوبکر طلحہ بن عبید الله
حضرت عائشہ
بنوز هرة
آمنہ والدہ آنحضرت (عبدالرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاصر
بنو عبد الدار
نضر بن الحارث
بنونوفل
مطعم بن عدی
مطعم
جبیر بن
عبد شمس
عبد مناف
بنوامیہ عتبہ بن ربیعه شیبہ بن ربیعہ
|
ابو حذیفہ
حضرت عثمان ابوسفیان عقبہ بن ابی معیط
ابو جہل بن ہشام ولید بن مغيرة
I
عکرمہ بن ابی جہل) خالد بن ولید
عبد العزیٰ
بنواسد
بنو ہاشم حضرت خدیجہ زبیر بن العوام
مطلب
I
I
عبد اللہ بن زبیر
عبيدة بن الحارث)
ابو صیفی عبد المطلب
اسد
فضلہ
حارث
زبیر
ابوطالب
عبد الله
ابولہب
عباس
حمزه
عقیل
حضرت علی محمد صلی اللہ علہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم) عبد اللہ بن عباس)
حضرت فاطمہ)
Page 110
۹۵
بعض افراد اس شجرہ میں ایسے نظر آئیں گے جن کی طرف کوئی قبیلہ منسوب نہیں حالانکہ وہ قریش میں
خاص شہرت رکھتے تھے.اس کی یہ وجہ ہے کہ عرب کی اقوام میں یہ دستور تھا کہ جب تک تو ایک شخص کی اولاد
میں اتحاد واتفاق رہتا تھا وہ اس کی طرف منسوب ہوتی تھی لیکن جب آپس میں عداوت اور رقابت ہو جاتی
تھی تو طرفین ایک واحد مورث کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے اپنے قبیلہ
کے واسطے مشترک مورث کے نیچے کسی اور مشہور آدمی کا نام اختیار کر لیتے تھے.یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے
ہیں کہ قصی کی اولاد قصی کی طرف منسوب نہیں بلکہ اُن میں سے کوئی بنو ہاشم بن گئے اور کوئی بنوامیہ اور کوئی
بنوعبدالدار وغیرہ.حالانکہ ان میں سے کوئی شخص بھی قصی کی سی شہرت
کا نہ تھا.قصی بن کلاب نضر بن کنانہ اور فہر بن مالک اپنے اپنے زمانہ میں بہت نامور اور صاحب اقتدار
اشخاص گذرے ہیں.ان کے بعد پانچویں صدی عیسوی میں یعنی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے قریباً سو ڈیڑھ سو سال پہلے قصی بن کلاب نے قریش میں بہت اقتدار حاصل کیا.یہ شخص ایک
غیر معمولی قابلیت کا مالک تھا.قبیلہ خزاعہ سے اس کے کعبہ کی تولیت چھین لینے کا ذکر اوپر گذر چکا ہے اور یہ
بھی بتایا جا چکا ہے کہ قصی نے تمام قبائلِ قریش کو اکٹھا کر کے مکہ میں آباد کیا.اسی واسطے اُسے مُجمع یعنی
جمع کرنے والا بھی کہتے ہیں مگر قصی کا کام اس پر ختم نہیں ہوتا بلکہ اس نے اپنی قوم کی ایک باقاعدہ تنظیم کی
اور مکہ میں گویا ایک جمہوری سلطنت کی بنیاد ڈالی ، جس کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ قصی نے کعبہ کی
تولیت اور قبیلہ قریش کے دوسرے انتظامی کاموں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ان فرائض کی ادائیگی
قریش کے مختلف قبائل کے رؤساء کے سُپر دکر دی.تولیت کعبہ کے مناصب کی تقسیم اس انتظام کے ماتحت کعبہ کی تولیت کے کام یہ مقرر کئے
گئے:
-1
-٢
سقایہ یعنی ایام حج میں حاجیوں کے واسطے پانی کا انتظام.چونکہ مکہ میں پانی کی بہت قلت تھی
کیونکہ زمزم کا چشمہ ایک عرصہ سے اٹ کر گم ہو چکا تھا اور اگر وہ ہوتا بھی تو چونکہ حج کے موقعوں پر
غیر معمولی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے اس لیے یہ کام خاص انتظام چاہتا تھا.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے وقت میں یہ کام بنو ہاشم میں تھا اور عباس بن عبدالمطلب کے سُپر دتھا.رفاده یعنی ایام حج میں غریب حاجیوں کی اعانت کا انتظام.اس کام کے لیے قریش میں ہر
سال چندہ جمع ہوتا تھا.زمانہ نبوی میں یہ کام بن نوفل میں تھا اور حارث بن عامر کے سپر دتھا.
Page 111
۹۶
حجابہ یعنی کعبہ کی دربانی اور کلید برداری.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ کام
بنوعبدالدار میں تھا اور عثمان بن طلحہ کے سپر دتھا.یہ تینوں کام قصی نے اپنی زندگی میں خود اپنے پاس
رکھے تھے.تقسیم نظام قبیلہ قریش کے عام انتظامی کاموں کی تقسیم بھی
-۲
-٣
-1
عقاب یعنی جنگوں وغیرہ کے موقع پر علمبرداری.یہ کام بھی قصی کے
اپنے پاس تھا اور اس کے بعد بنوعبدالدار میں آیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ کام
طلحہ بن ابی طلحہ کے سپر د تھا.اسی کا دوسرا نام لواء تھا.قیادہ یعنی جنگوں اور قافلوں میں کمان.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ کام بنوامیہ
میں تھا اور ابوسفیان کے سپر د تھے.سفارت یعنی قریش کی طرف سے بوقت ضرورت کسی دوسرے قبیلہ یا حکومت کی طرف سفیر
ہو کر جانا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ کام بنو عدی میں تھا اور حضرت عمرؓ کے
سیر د تھا.دیات اور مغارم یعنی باہم لڑائیوں میں خون بہا وغیرہ کا فیصلہ کرنا.یہ کام بنوتیم میں تھا اور
حضرت ابو بکر کے سپر د تھا.- قبه یعنی جنگوں میں سوار فوج کی افسری اور کیمپ کا انتظام.یہ منصب خاندان مخزوم میں تھا اور
-1
ولید بن مغیرہ کے سپر د تھا.از لام یعنی فال کشی کا انتظام.یہ کام بنو حج میں تھا اور صفوان بن امیہ کے سپر دتھا.مشورہ یعنی اہم اجتماعی کاموں میں بین القبائل مشورہ کا انتظام.یہ کام بنو اسد میں تھا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یزید بن ربیعتہ الا سود کے سپر دتھا.قضاء یعنی مقدمات کا فیصلہ.یہ کام بنو سہم میں تھا اور حارث بن قیس کے سپر دتھا.وغیرہ وغیرہ.دار الندوة قصی نے کعبہ کے پاس ایک دارالندوہ بھی بنایا جس میں قریش اپنے تمام قومی کام سرانجام
دیتے تھے اور یہیں سردارانِ قریش باہم مشورہ کے لیے جمع ہوتے تھے.یہ گویا قریش کا
کونسل ہال تھا.ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ بھی سردارانِ قریش نے دار الندوة
میں ہی کیا تھا.دارالندوہ کے مشورہ میں شریک ہونے کے لیے یہ ایک شرط تھی کہ عمر چالیس سال سے کم
Page 112
۹۷
نہ ہو.بیاہ شادی کے لیے بھی قریش دارالندوہ میں ہی جمع ہوتے تھے اور یہیں اپنی رسوم ادا کرتے تھے.اگر کہیں جنگ پر باہر جانا ہوتا تھا یا کسی تجارتی قافلہ کو روانہ ہونا ہوتا تو لوگ یہیں سے جمع ہو کر روانہ ہوتے
تھے.دارالندوہ کا انتظام قصی نے خود اپنے پاس رکھا تھا.قصی کے ان غیر معمولی کارناموں نے اسے تمام اطراف عرب میں مشہور کر دیا تھا اور قریش کا تو گویا
وہ ایک قسم کا بادشاہ تھا، مگر اس انتظام سلطنت سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ قریش کے اندر کوئی با قاعدہ سلطنت تھی
یا یہ کہ افراد کی آزادی پر کوئی خاص پابندیاں تھیں بلکہ یہ انتظام صرف اہم قومی معاملات کو آسانی کے ساتھ
طے کرنے کے واسطے کیا گیا تھا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ فرائض کی یہ تفصیلی تقسیم سب کی سب قصی کے اپنے
ہاتھ سے مکمل ہوئی ہو بلکہ ممکن ہے کہ کوئی شاخ اس سے پہلے کی ہو یا کوئی شاخ بعد میں حسب ضرورت قائم
کی گئی ہومگر بہر حال اس کام کی اصولی داغ بیل قصی ہی کے ہاتھ سے قائم ہوئی تھی.قصی کے چار بیٹے تھے.عبدالدار، عبدالعزکی ، عبد مناف اور عبد قصی.عبدالدار چونکہ بڑا
عبد مناف
تھا اس لیے قصی نے مرتے ہوئے اپنے تمام کام یعنی کعبہ کی تولیت کے تینوں مناصب اور
دارالندوة اورلو اء اس کے سپر د کئے ،مگر عبدالدار اپنے باپ کی قابلیت کا آدمی نہ تھا اس لیے قریش کی
عام ریاست عبد مناف نے حاصل کی جو بہت لائق اور قابل آدمی تھا.عبد مناف کے چار بیٹے تھے.عبد شمس ، مطلب، ہاشم اور نوفل.یہ چاروں باپ کی طرح قابل تھے.چنانچہ عبد مناف کی وفات کے
بعد ان سب نے مل کر اس بات کی کوشش کی کہ عبدالدار کی اولاد سے کعبہ کی تولیت چھین لیں.اس پر
طرفین
کا باہم جھگڑا ہو گیا.قریش کے بعض قبائل ایک طرف ہو گئے اور دوسرے دوسری طرف.اور قریب
تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی مگر آخر صلح صفائی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا اور دو مناصب یعنی رفادہ اور سقایہ
بنوعبد مناف کومل گئے اور باقی تین مناصب یعنی دارالندوہ کا انتظام لواء اور حــجــابـه بنوعبدالدار کے
پاس رہے.بنو عبد مناف نے آپس میں مشورہ کے ساتھ سقایہ اور رفادہ کا متولی ہاشم کو مقرر کر دیا.ہاشم نہایت قابل ، معاملہ فہم اور سخی آدمی تھا.اُس نے حاجیوں کو بہت آرام پہنچایا اور قریش کے
سامنے بہت زوردارا پہلیں کر کر کے اُن کی مختلف ضروریات کے واسطے سامان مہیا کئے.اُس کے
زمانہ میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا تو اس نے اپنے پاس سے اخراجات کر کے قحط کے ایام میں غرباء کو کئی طرح
سے مدد دی.ان فیاضیوں کی وجہ سے ہاشم کا نام بہت شہرت پا گیا.اس کے علاوہ ہاشم نے خود جا جا کر
ا : ابن سعد
Page 113
۹۸
رومی اور غسانی فرمانرواؤں سے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے حقوق حاصل کئے اور ہاشم کے
دوسرے بھائیوں نے بھی کم و بیش اسی قسم کی خدمات انجام دیں.چنانچہ قریش کے تجارتی قافلوں کی شام
اور یمن وغیرہ کی طرف آمد و رفت ہاشم ہی کے زمانہ میں شروع ہوئی.عموماً سردیوں میں تجارتی قافلے یمن
کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف اور یہ دونوں سلسلے رِحْلَتُ الشّتاء اور رِحُلَتُ
الصيف کہلاتے تھے یا
امیہ کی رقابت باشم کی اس ترقی کو دیکھ کر ہاشم کے بھیجے امیہ بن عبد الشمس کے دل میں حسد پیدا ہوا
اور اس نے ہاشم کا مقابلہ کرنا چاہا اور اسی کی طرح لوگوں میں سخاوت کر کے نام پیدا
کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا.بلکہ اس ناکامی سے اُلٹا قریش کے ہنسی مذاق کا نشانہ بن گیا.آخر
امیہ کو اتنا جوش آیا کہ اُس نے ہاشم کو کھلا چیلنج دے کر اپنے مقابلہ کے لئے بلایا.ہاشم نے پہلے تو توجہ نہ کی ،
لیکن آخر قریش کے کہنے سننے سے جو اس قسم کا تماشہ دیکھنے کے خواہشمند رہتے تھے ، ہاشم راضی ہو گیا اور شرط
یہ ٹھہری کہ کوئی ثالث ان کی بڑائی کا فیصلہ کرے اور جو ہارے وہ دوسرے کو پچاس اونٹ دے.اور دس
سال کے لیے مکہ سے جلا وطن کیا جاوے.ایک کا ہن جو قبیلہ خزاعہ سے تھا ثالث مقرر ہوا.اُس نے اپنی
کا ہنی زبان کے دو چار فقرے بول کر ہاشم کے حق میں فیصلہ دے دیا.چنانچہ امیہ نے پچاس اونٹ ہاشم
کے حوالے کئے اور مکہ سے نکل گیا اور دس سال تک شام وغیرہ میں پھرتا رہا.مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ پہلی
عداوت اور رقابت ہے جو بنو ہاشم اور بنوامیہ کے درمیان پیدا ہوئی.ہاشم کے بعد عبدالمطلب بن ہاشم نے
بھی اپنے زور کے ساتھ بنو ہاشم کو بنوامیہ پر غالب رکھا، لیکن عبدالمطلب کی وفات کے بعد ہاشم کے پوتوں
میں کوئی اس جیسا صاحب اثر شخص نہ نکلا اس لیے بنوامیہ آہستہ آہستہ زور پکڑ گئے اور ہاشم کا خاندان غربت
کی حالت میں مبتلا ہوکر کمزور ہو گیا.ہاشم ایک دفعہ شام کی طرف بغرض تجارت نکلا تو راستہ میں میٹرب یعنی مدینہ بھی ٹھہرا.وہاں ہاشم نے
قبیلہ خزرج کی شاخ بنو نجار کی ایک لڑکی سلمی سے شادی کی جس سے مدینہ میں ہی سلمی کے ہاں ایک لڑکا پیدا
ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا.مطلب
ا: ابن سعد
کچھ عرصہ کے بعد ہاشم کا باہر سفر میں ہی انتقال ہو گیا.وفات کے وقت اُس کے چارلڑ کے
تھے.ابو صینی ، اسد ، فضلہ اور شیبہ.مگر یہ چاروں چونکہ کم عمر تھے اور شیبہ تو مدینہ میں ہی تھا اس
Page 114
۹۹
لیے ہاشم کی وفات پر اس کی جگہ اس کے بڑے بھائی مطلب نے لی یعنی سقایہ اور رفادہ کے کام اس کے
سپرد ہوئے.جب مطلب کو کسی شخص نے اس کے بھتیجے شیبہ بن ہاشم کی ہوشیاری اور ہونہاری کی خبر دی
تو وہ فوراً مدینہ جا کر شیبہ کو لے آیا.مکہ میں جب چا بھیجے داخل ہوئے تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید
مطلب کوئی غلام کا لڑکا لایا ہے.اسی لیے شیبہ کا نام عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام مشہور ہو گیا.یہ وہی
عبد المطلب ہیں جو ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور جن کی آغوش میں آپ نے اپنی
عمر کے ابتدائی آٹھ سال گزارے.عَبْدَ الْمُطَّلب مطلب کی پوزیشن چونکہ صرف ایک گارڈین کی تھی اس لیے اس کی تولیت کے وہ
مناصب جو عبد مناف کے گھرانے میں تھے اس کی وفات کے بعد عبدالمطلب کو ملے
کیونکہ اپنے بھائیوں میں یہی سب سے ہوشیار تھا.عبدالمطلب نہایت سمجھدار اور قابل شخص تھا مگر چونکہ اس
وقت وہ نوجوان تھا اور اپنی عمر کا ایک حصہ باہر گزار کر آیا تھا، اس لیے شروع شروع میں اُسے اپنی پوزیشن کو
قائم رکھنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوا.چنانچہ سب سے پہلے تو عبدالمطلب کی وراثت میں اس کے
چچا نوفل بن عبد مناف نے جھگڑا کیا.عبدالمطلب نے قریش سے اپیل کی لیکن قریش نے اس معاملہ میں
دخل دینے سے انکار کر دیا.جس پر عبدالمطلب نے یثرب میں اپنی ننھیال بن نجار کو کہلا بھیجا کہ میرا چچا میری
وراثت میں بے جا مداخلت کرتا ہے.وہاں سے فوراً اسی بہادر اپنے نواسے کی مدد کو مکہ پہنچ گئے.جس
وقت یہ لوگ مکہ میں پہنچے تو اس وقت نوفل چند آدمیوں کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا تھا.انہوں نے آتے
ہی اُسے کہا کہ ہمارے نواسے شیبہ بن ہاشم کو اس کا سارا اور نہ دے دو.ورنہ اچھا نہ ہو گا.نوفل مرعوب ہو گیا
اور اُس نے مداخلت سے ہاتھ کھینچ لیا.بنوعبد الشمس اور بنو ہاشم کے درمیان رنجش پیدا ہو جانے کا ذکر اوپر
گذر چکا ہے.اب بنو نوفل کے تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے.گویا عبد مناف بن قصی کے باقی بیٹوں میں سے
بنو ہاشم کے ساتھ صرف بنو مطلب کے تعلقات اچھے رہے اور اس طرح اس خاندان میں دو پارٹیاں بن
گئیں.ایک طرف بنو ہاشم اور بنو مطلب تھے اور دوسری طرف بنو نوفل اور بنو عبد شمس.اس جتھہ بندی کا
یہاں تک اثر تھا کہ جب بنو ہاشم اور دیگر مسلمانوں کو کفار مکہ نے شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تو اس
وقت بھی بنو مطلب نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا اور قریش سے الگ رہے مگر بنو نوفل اور بنوعبد شمس نے کفار کا
ساتھ دیا اور بنو ہاشم کی مخالفت کی.مطلب نے جو حسنِ سلوک کا معاملہ عبدالمطلب سے کیا تھا وہ بھی
ل : ابن ہشام
Page 115
10.بنو مطلب اور بنو ہاشم کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کا موجب ہوا اور بنو مطلب ہمیشہ بنو ہاشم کے
ساتھ ایک جان ہو کر رہے؛ چنانچہ اسی رشتہ اتحاد کا نتیجہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خمس کی تقسیم
میں سے ( یعنی مال غنیمت میں سے وہ پانچواں حصہ جو اللہ اور اُس کے رسول کے قریبی رشتہ داروں اور
مشترک اسلامی ضروریات کے لیے الگ کیا جاتا تھا) بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب کاحصہ بھی نکالتے تھے اور
جب بنو نوفل اور بنو عبد شمس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری رشتہ کی بنا پر درخواست کی کہ
بنو مطلب کی طرح اُن
کو بھی شمس سے حصہ ملا کرے تو آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب تو
ایک ہی ہیں لیے
چاہ زمزم کی تلاش چاہ زمزم جو مکہ کی آبادی کا پہلا سبب تھا صدیوں سے بند ہو کر گم ہو چکا تھا.جب
عبدالمطلب کے ہاتھ میں سقایۃ الحاج کا کام آیا تو اُس نے ایک خواب کی
بنا پر اس کھوئے ہوئے چشمہ کا نشان تلاش کرنا چاہا.چنانچہ وہ اور اس کا لڑکا حارث اس کی تلاش میں
مصروف ہوئے لیکن قریش میں سے کسی نے بنو ہاشم کی مدد نہ کی.بلکہ بعض نے الٹا باپ بیٹے کا مذاق
اڑایا.عبدالمطلب نے اس وقت اپنی کمزوری پر شرم و غیرت کے جوش میں آکر نذرمانی کہ اگر خدا اُسے
دس بچے دے گا اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں گے تو اُن میں سے ایک کو وہ خدا کی راہ
میں قربان کر دے گا.کچھ عرصہ کی محنت کے بعد عبدالمطلب کو زمزم کی جگہ کا نشان مل گیا جسے کھودنے سے
یہ پرانا چشمہ پھر نکل آیا اور اس کے ساتھ ہی وہ دفینہ بھی برآمد ہوا جو قبیلہ جرھم نے مکہ چھوڑتے ہوئے
اُس میں دفن کر دیا تھا.اس غیر مترقبہ واقعہ نے تمام قریش پر عبدالمطلب کا سکہ بٹھا دیا اور گوانہوں نے
شروع میں عبدالمطلب کے ساتھ دفینہ کے بارے میں جھگڑا کرنا چاہا، لیکن بالآ خر مرعوب ہو کر خاموش ہو
گئے.پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی بڑائی کے اس قدر قائل ہو گئے کہ بالآ خر عبدالمطلب کی یہ حالت تھی کہ تمام
قریش اُسے اپنا نہایت واجب الاحترام سردار جانتے تھے کے
عبدالمطلب کا بڑا ہم مجلس ابو سفیان کا والد حرب بن امیہ تھا لیکن بالآ خر عبدالمطلب کی ترقی نے اس
کے دل میں بھی حسد کی چنگاری پیدا کر دی اور اُس نے اپنے باپ کی طرح بنو ہاشم سے مقابلہ کرنا چاہا لیکن
ناکام رہا.اس منافرت کے بعد عبدالمطلب کی مجلس زیادہ تر عبد اللہ بن جدعان تیمی کے ساتھ رہی جو مکہ کا
ا : بخاری باب مناقب قریش
۳ : ابن سعد وابن ہشام
: ابن سعد ذکر نذر عبد المطلب
Page 116
1+1
ایک شریف مزاج رئیس تھا.عبداللہ چاہ زمزم کے واقعہ کے بعد عبدالمطلب بڑا صاحب اثر ہو گیا اور خدا کی قدرت کہ اس کی اولاد
بھی جلد جلد بڑھنے لگی.حتی کہ آخر ان کی تعداد دس تک پہنچ گئی.جب یہ لڑ کے جوان ہو گئے
اور ایفائے نذر کا وقت آ گیا تو عبدالمطلب اُن سب کو اپنے ساتھ لے کر کعبہ کی طرف گیا اور وہاں جا کر
ھبل کے سامنے قرعہ اندازی کی.اللہ کی قدرت کہ قرعے کا تیر سب سے چھوٹے لڑکے عبداللہ کے نام نکلا
جوعبدالمطلب کوسب سے زیادہ عزیز تھا.اس وقت عبدالمطلب کی جو حالت تھی وہ بیان میں نہیں آ سکتی ، مگر
عبدالمطلب قول کا پکا تھا اور نذر بہر حال پوری کرنی تھی اس لیے وہ عبداللہ کو لے کر ذبح کرنے کے واسطے
روانہ ہوا اور عبد اللہ بھی سر تسلیم خم کئے اپنے باپ کے ساتھ ہو لیا جب رؤسائے قریش کو اس کا علم ہوا تو
انہوں نے عبدالمطلب کو اس سے روکا اور آخر ایک واقف کار کے مشورہ سے یہ قرار پایا کہ عبداللہ اور دس
اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے اور اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکلے تو عبداللہ کی جگہ دس اونٹ قربان کر
دیئے جاویں کہ یہی اس زمانے میں ایک آدمی کا خون بہا تھا.چنانچہ عبدالمطلب نے عبد اللہ اور دس اونٹوں
کے درمیان قرعہ ڈالا ،مگر پھر بھی تیر عبداللہ ہی کے نام نکلا.عبدالمطلب نے دس اور زائد کئے اور ہمیں پر قرعہ
ڈالا ، لیکن اب کی دفعہ بھی عبد اللہ ہی کا نام نکلا.دس اور زائد کئے گئے ، لیکن پھر بھی عبداللہ ہی کا نام تھا.چالیس، پچاس، ساٹھ ، ستر ، اسی ، نوے مگر ہر دفعہ عبداللہ کا نام آتا تھا.آخر سو تک نوبت پہنچی اور اب کی
مرتبہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلا.لیکن اس پر بھی عبد المطلب نے مزید تسلی کے واسطے پھر دو دفعہ قرعہ ڈالا مگر
دونوں دفعہ اونٹوں کا نام نکلا.جس پر سو اونٹ ذبح کئے گئے اور عبد اللہ کی جان بچی..اس وقت سے قریش
میں ایک آدمی کا خون بہا سو اونٹ مقرر ہو گئے کے
اصحاب الفیل عبدالمطلب کے زمانہ میں یمن کا علاقہ افریقہ کے ملک حبشہ کے ماتحت تھا جو ان ایام
میں ایک طاقتور حکومت کا مرکز تھا اور چونکہ حبشہ ایک عیسائی ملک تھا اس لئے یمن کا
گورنر بھی عیسائی ہوا کرتا تھا.عبدالمطلب کے زمانہ میں یمن کے والی کا نام ابر ہتہ الاشرم تھا.یہ شخص کعبہ
سے سخت دشمنی رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح عرب کے لوگوں کو کعبہ سے پھیر دے.چنانچہ اُس نے کعبہ
کے مقابلہ پر یمن میں ایک معبد تیار کیا اور لوگوں میں تحریک کی کہ وہ بجائے کعبہ کے اس عبادت گاہ کے حج
کے لیے آیا کریں.عرب کی فطرت بھلا اس بات کو کس طرح برداشت کر سکتی تھی کہ عرب کی سرزمین میں
ل : ابن سعد ذکر عبدالمطلب سے : ابن ہشام وابن سعد وزرقانی
: ابن سعد
Page 117
۱۰۲
کعبہ کے مقابلہ پر کوئی اور معبد قائم ہو.چنانچہ لکھا ہے کہ ایک عرب نے جوش میں آ کر اس معبد میں جا کر
پاخانہ کر دیا.ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے غصہ میں آکر ارادہ کیا کہ مکہ پر فوج کشی کر کے کعبہ کو
مسمار کر دے چنانچہ اُس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے اجازت لی اور ایک بڑے بھاری لشکر کے
ساتھ جس کی تعداد بعض روایات سے ساٹھ ہزار پتہ لگتی ہے اور بہر حال وہ ہزاروں پر مشتمل تھا ، یمن سے
نکلا اور راستہ میں مختلف قبائل عرب کو شکست دیتا ہوا مکہ کے قریب پہنچ گیا اور شہر کے سامنے اپنی فوجیں
ڈال دیں.جب قریش کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت پریشان ہوئے ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کے مقابلہ
کی تاب نہیں رکھتے.چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس بطور وفد کے روانہ کیا.عبدالمطلب کی
وجیہ شکل اور نجابت نے ابرہہ پر بہت اچھا اثر کیا اور وہ اس سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا اور اپنے
ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو وہ کیا چاہتے ہیں.عبد المطلب نے جو شاید پہلے سے اس گفتگو کے طریق کو
سوچ کر آیا تھا کہا کہ آپ کی فوج نے میرے اُونٹ پکڑ لیے ہیں وہ مجھے دلوا دئیے جائیں.اُس نے اونٹ
تو واپس دلوا دیئے ، مگر جو اثر اس کے دل پر عبد المطلب کی وجاہت اور قابلیت کا ہوا تھا وہ سب جاتا رہا اور
اُس نے مُنہ بنا کر کہا میں تمہارے کعبہ کو مسمار کرنے کے واسطے آیا ہوں ، مگر تم نے اس کی فکر نہ کی اور
اپنے اونٹوں کی فکر کی.عبدالمطلب نے بے پروائی کے انداز میں کہا.أَنَا رَبُّ الْإِبِلِ وَ لِلْبَيْتِ
رَبِّ يَمْنَعُهُ - یعنی میں تو صرف اُونٹوں کا مالک ہوں ، اس لیے مجھے ان کا فکر ہے.مگر اس گھر کا بھی ایک
مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا.ابرہہ نے یہ جواب سنا تو بہت بگڑا اور کہا کہ.”اچھا پھر میں
دیکھوں گا کہ اس گھر کا مالک مجھے اس سے کس طرح روکتا ہے.چنانچہ وہ اپنے لاؤلشکر کو لے کر آگے بڑھا
مگر خدائی تصرف ایسا ہوا کہ جو نہی کہ اس ہاتھی کا رُخ جس پر ابر ہر سوار تھا مکہ کی طرف کر کے اُسے چلایا گیا
تو وہ چلنے سے رک گیا اور باوجود انتہائی کوشش کے آگے نہ بڑھا اور پھر اس لشکر پر ایسی آفت آئی کہ لشکر کا
لشکر تباہ ہوکر پرندوں کی خوراک بن گیا.اس کی تفصیل روایات میں یوں بیان ہوئی ہے کہ جب یہ لشکر مکہ
کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، تو اُس وقت خدائی تصرف کے ماتحت اُن کے اُوپر سے ایسے پرندوں کے غول
گذرے جن کے پنجوں میں ایسی زہر آلود مٹی کے ریزے لگے ہوئے تھے کہ جس جس کے اوپر یہ ریزے
گرتے تھے وہ ایک چیچک کی سی مہلک اور متعدی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا اور جب لشکر میں ایک دفعہ یہ
بیماری پھوٹی تو پھر بڑی سرعت سے ایک سے دوسرے کو لگتی چلی گئی اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ
متعدی بیماریاں بسا اوقات مٹی کے ذرات یا دوسرے ذرائع سے پھیل جاتی ہیں.پس بالکل ممکن ہے کہ یہ
Page 118
۱۰۳
پرندے کسی ایسی جگہ سے اُٹھ کر آئے ہوں جو کسی متعدی بیماری کے جراثیم سے ملوث ہو اور اس طرح اُن
کے واسطے سے لشکر میں کوئی چیچک وغیرہ کی مہلک بیماری پھیل گئی ہو.چنانچہ ابر ہ کے متعلق تو خاص طور
پر ذکر آتا ہے کہ اُسے کوئی ایسی بیماری ہوئی تھی ، جس سے اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا تھا.قرآن شریف میں اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے:
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحُبِ الْفِيْلِ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيْلٍ وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَن تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ
مِنْ سِجِيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ 0
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ کیا اُس
نے اُن کی تجاویز کو خاک میں نہیں ملا دیا ؟ اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے جوان
پر مٹی کے پتھریلے ریزے مارتے تھے.اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بوسیدہ بھوسے کی
طرح کر دیا.“
ابرھہ کا یہ حملہ تاریخ میں اصحاب الفیل کا حملہ کہلاتا ہے یعنی ہاتھی والوں کا حملہ.جس کی وجہ یہ ہے
کہ ابر ہہ کی فوج میں ایک ہاتھی یا بعض روایتوں کی رو سے متعدد ہاتھی بھی تھے.چونکہ قریش مکہ کے لیے
ہاتھی ایک عجیب اور نئی چیز تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ، اس لیے انہوں نے نہ صرف حملہ آوروں
کا نام اصحاب الفیل رکھا بلکہ اس سال کا نام بھی عام الفیل رکھ دیا.اصحاب الفیل کی تباہی سے کعبتہ اللہ کی
عزت اور قریش کا رُعب بہت بڑھ گیا اور دوسرے قبائل عرب انہیں آگے سے بھی زیادہ عزت و احترام
کی نظر سے دیکھنے لگے.عبد اللہ کی شادی اصحاب الفیل کے واقعہ سے چند ماہ پیشتر عبدالمطلب نے آمنہ بنت وہب سے جو
قریش کے قبیلہ بنوزہرہ میں سے ایک معزز گھرانے کی نہایت شریف لڑکی تھی اپنے
لڑکے عبداللہ کی شادی کی.اُس وقت عبد اللہ کی عمر پچیس سال کی یا بعض روایتوں کی رو سے سترہ سال کی
تھی.یہ اسی موقع پر آمنہ کی ایک چا زاد بہن ہالہ بنت وہب سے عبدالمطلب نے خود بھی شادی کی.حمزہ اسی
ہالہ کے بطن سے پیدا ہوئے.ل : ابن ہشام وزرقانی
ے : ابن ہشام
: سورۃ الفیل آیت ۲ تا ۶
: خمیس و زرقانی
Page 119
۱۰۴
عبداللہ کی وفات عبداللہ کو نکاح کے بعد مصلحتِ الہی سے زیادہ مہلت نہیں ملی.چنانچہ تھوڑے ہی
عرصہ کے بعد جب وہ تجارت کے لیے شام کو گئے تو واپسی پر بیمار ہو کر یثرب میں
ٹھہر گئے اور وہیں انتقال کیا اور اپنے رشتہ دار قبیلہ بنونجار کے درمیان دفن ہوئے.اُس وقت اُن کی زوجہ
آمنہ حمل سے تھیں یا اپنے اس بچہ کے لیے جو ابھی اپنی ماں کے بطن میں ہی تھا عبداللہ نے جو تر کہ چھوڑا
وہ قابل ذکر ہے.یعنی پانچ اونٹ.چند بکریاں اور ایک لونڈی اُم ایمن.یہ تر کہ اس کے لیے تھا جس
نے ہر دو عالم کا بادشاہ بننا تھا.عبدالمطلب کو جب اپنے فرزند عبداللہ کی بیماری کی خبر پہنچی تو اس نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو
مدینہ کی طرف روانہ کیا تا کہ وہ مدینہ جا کر عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آوے مگر جب حارث مدینہ پہنچا، تو
عبداللہ فوت ہو چکے تھے.اُس نے واپس آ کر بڑھے باپ کو خبر دی کہ تیرا عزیز لڑکا اس جہان فانی سے
گذر چکا ہے.اس وقت عبدالمطلب کو جو صدمہ ہوا وہ قیاس ہی کیا جا سکتا ہے مگر اس صدمہ سے بہت
بڑھ کر وہ صدمہ ہو گا جو آمنہ کے دل کو پہنچا جس کا شوہر اس غریب الوطنی کی حالت میں شادی سے تھوڑے
ہی عرصہ بعد اسے داغ ہجرت دے گیا.نئی نئی شادی کی حالت میں کم عمر لڑکیاں جو طبعا اپنے اندر شرم وحیا
کا زیادہ مادہ رکھتی ہیں ایسے موقعوں پر اپنے غم والم کا اظہار نہیں کر سکتیں.اس لیے اُن کو اندر ہی اندر
صدمه برداشت کرنا پڑتا ہے.اس سے اس تکلیف کا اندازہ ہوسکتا ہے جو اس موقع پر حضرت آمنہ کو
اٹھانی پڑی ہوگی.مگر خدا کی تسلی جلد ہی آمنہ کے سہارے کے لیے آئی.چنانچہ انہی ایام میں آمنہ نے
ایک خواب دیکھا کہ اُن کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور انہیں خواب میں ہی بتایا گیا کہ اس لڑکے کا نام
محمد رکھنا.نیز انہوں نے یہ بھی خواب دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک چمکتا ہوا نور نکلا ہے اور دُور دراز
ملکوں میں پھیل گیا ہے.: ابن سعد وزرقانی جلد اوّل صفحه ۱۰۹
: طبقات ابن سعد
سے : سیرۃ ابن ہشام وزرقانی
Page 120
۱۰۵
ولادت با سعادت
ابتدائی زندگی
آمنہ کے نور کے ظہور کا وقت نزدیک آ رہا تھا اور وضع حمل کے دن قریب تھے.وہ شعب بنی ہاشم میں رہتی تھیں اور اس وقت کے انتظار میں تھیں کہ جب اُن
کے مرحوم شوہر کی یاد کو زندہ رکھنے والا بچہ دنیا کی روشنی میں آوے اور ان کے صدمہ رسیدہ دل کے لیے
تسکین و راحت کا موجب ہو.چنانچہ واقعہ اصحاب الفیل کے چھپیں روز بعد ۱۲ ؍ ربیع الاول مطابق
۲۰ را گست ۷۰ ۵ عیسوی کو یا ایک جدید اور غالباً صحیح تحقیق کی رُو سے ۹ ربیع الاول مطابق ۲۰ را پریل ۵۷۱ء
بروز پیر بوقت صبح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یا واقعہ فیل کے اس قدر متصل آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہونا اپنے اندر یہ خدائی اشارہ رکھتا تھا کہ جس طرح خدا نے کعبہ کے خلاف
اس ظاہری حملہ کو خائب و خاسر کیا ہے اسی طرح اب وقت آتا ہے کہ دینِ الہی کے مقابل پر باطل پرستی کا
سر کچلا جائے اور قرآن شریف میں اصحاب الفیل کے حملہ کا ذکر بھی بظاہر اسی غرض و غایت کے ماتحت نظر
آتا ہے.بہر حال بچہ کے پیدا ہوتے ہی آمنہ نے عبدالمطلب کو اطلاع بھجوا دی جو سنتے ہی فورا خوشی کے
جوش میں آمنہ کے پاس چلے آئے.آمنہ نے اُن کے سامنے لڑکا پیش کیا اور کہا کہ میں نے ایک خواب
میں اس کا نام محمد دیکھا تھا.عبدالمطلب بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے اور وہاں جا کر
خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کا نام محمد رکھا جس کے معنے ہیں ”بہت قابلِ تعریف‘ اور پھر اسے واپس لا کر خوشی
خوشی ماں کے سپر د کر دیا ہے
مؤرخین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق بعض عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں.مثلاً یہ کہ اس وقت کسری شہنشاہ ایران کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اور
فارس کا مقدس آتشکدہ جو صدیوں سے برابر روشن چلا آتا تھا دفعہ بُجھ گیا اور بعض دریا اور چشمے خشک ہو
گئے اور یہ کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی رنگا رنگ کے کرشمے ظاہر ہوئے وغیر ذالک.مگر یہ روایتیں عموماً
ل : محمود پاشا مصری
: ابن ہشام
Page 121
1+7
کمزور ہیں.یہ بھی روایت آتی ہے جو غالباً صحیح ہے کہ آپ کے ولادت کے زمانہ میں آسمان پر غیر معمولی
کثرت کے ساتھ ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے تھے.اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر مخنتون پیدا ہوئے.اگر یہ درست ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ بعض
اوقات بچوں میں اس قسم کی قدرتی باتیں دیکھی گئی ہیں.ایک اور بات بھی آپ میں قدرتی طور پر تھی اور وہ
یہ کہ آپ کی پشت پر بائیں جانب ایک گوشت کا اٹھا ہوا ٹکڑا تھا جو عام طور پر مسلمانوں میں ختم نبوت یعنی
مُہر نبوت کے نام سے مشہور ہے..رضاعت اور ایام طفولیت مکہ کے شرفاء میں یہ دستور تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ نہ پلاتی
تھیں بلکہ عام طور پر بچے شہر سے باہر بدوی لوگوں میں دائیوں کے
سپر د کر دیے جاتے تھے اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جنگل کی کھلی ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور طاقتور ہوتے
تھے اور زبان بھی عمدہ اور صاف سیکھتے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع شروع میں آپ کی والدہ نے اور پھر ثویبہ نے دُودھ پلایا.ثویبہ
آپ کے چچا ابولہب کی لونڈی تھی جسے ابولہب نے اپنے یتیم بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا.اسی ثویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا.گویا اس طرح حمزہ جو آپ کے حقیقی چاتھے دودھ کے رشتہ
سے آپ کے بھائی بن گئے.تویہ کی یہ چند دن کی خدمت آنحضرت صلعم کبھی نہیں بھولے.جب تک وہ
زندہ رہی آپ ہمیشہ اس کی مددفرماتے رہے اور اُس کے مرنے کے بعد بھی آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا
اس کا کوئی رشتہ دار باقی ہے.مگر معلوم ہوا کہ کوئی نہ تھا.ثویبہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مستقل طور پر حلیمہ کے سپرد ہوئی جو قوم
ہوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون تھی اور دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر مکہ میں دایہ کے طور پر
کسی بچے کی تلاش میں آئی تھی.ایک یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے حلیمہ ابتداء خوش نہ تھی ،
کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ کوئی زندہ باپ والا بچہ ملے جہاں زیادہ انعام واکرام کی اُمید ہو سکتی تھی.چنا نچہ شروع میں اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے سے تامل کیا مگر جب کوئی
اور بچہ نہ ملا اور اس کے ساتھ کی سب عورتوں کو بچے مل چکے تھے تو وہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھ کر آپ
کو اپنے ساتھ لے گئی لیکن جلد ہی حلیمہ کو معلوم ہو گیا کہ جو بچہ وہ اپنے ساتھ لائی ہے.اس کا ستارہ
ل : زرقانی جلد اصفحه ۱۲۲ و خمیس جلد اصفحہ ۲۲۷ - ۲۲۸ ۲ : زرقانی و خمیس سے : زرقانی
Page 122
۱۰۷
بہت بلند ہے.چنانچہ اُس کی اپنی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم
پر بہت تنگی کا وقت تھا ، مگر آپ کے آنے کے ساتھ یہ تنگی فراخی میں بدل گئی اور ہماری ہر چیز میں
برکت نظر آنے لگی.حلیمہ کا وہ لڑکا جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیتا تھا اس کا نام
عبد اللہ تھا اس کی ایک بڑی بہن بھی تھی جس کا نام شیما تھا جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت
عزیز رکھتی تھی.دو سال کے بعد جب رضاعت کی مدت پوری ہوئی تو دستور کے مطابق حلیمہ آپ کو لے کر مکہ
میں آئی مگر اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو چکی تھی کہ اُس کا دل چاہتا تھا کہ اگر ممکن ہو تو
آپ کی والدہ سے اجازت لے کر آپ کو پھر واپس لے جاوے؛ چنانچہ اُس نے باصرار کہا کہ ابھی اس بچہ کو
کچھ عرصہ اور میرے پاس رہنے دو.میں اس کا ہر طرح خیال رکھوں گی.آمنہ نے پہلے تو انکار کیا ، مگر پھر
اس کے اصرار کو دیکھ کر اور یہ خیال کر کے کہ مکہ کی آب و ہوا سے باہر کی آب و ہوا اچھی ہے اور ان ایام
میں مکہ کی آب وہوا کچھ خراب بھی تھی آمنہ نے مان لیا اور حلیمہ آپ کو لے کر پھر خوش خوش اپنے گھر لوٹ
گئی اور اس کے بعد قریباً چار سال کی عمر تک آپ حلیمہ کے پاس رہے اور قبیلہ بنوسعد کے لڑکے لڑکیوں میں
کھیل کود کر بڑے ہوئے.اس قبیلہ کی زبان خاص طور پر صاف اور فصیح تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی یہی زبان
سیکھی.حلیمہ آپ کو بہت عزیز رکھتی تھی اور قبیلہ کے تمام لوگ آپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے لیکن
جب آپ کی عمر چار سال کی ہوئی تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حلیمہ خوفزدہ ہوگئی اور آپ کو
واپس مکہ میں لا کر آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا.یہ واقعہ تاریخ میں اس طرح پر مذکور ہے کہ ایک دفعہ
آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مل کر کھیل رہے تھے اور کوئی بڑا آدمی پاس نہ تھا کہ اچانک دوسفید پوش
آدمی نظر آئے اور انہوں نے آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا.یہ نظارہ دیکھ کر
آپ کا رضائی بھائی عبداللہ بن حارث بھاگا ہوا گیا اور اپنے ماں باپ کو اطلاع دی کہ میرے قریشی
بھائی کو دو آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کا سینہ چاک کر رہے ہیں.حارث اور حلیمہ یہ سنتے ہی
بھاگے آئے تو دیکھا کہ کوئی آدمی تو وہاں نہیں ہے ، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوفزدہ حالت
میں کھڑے ہیں اور چہرہ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے.حلیمہ نے آگے بڑھ کر آپ کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا
” بیٹا کیا بات ہوئی ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ وہ کوئی چیز میرے سینہ
Page 123
1+A
میں تلاش کرتے تھے.جسے انہوں نے نکال کر پھینک دیا.پھر حلیمہ اور حارث آپ کو اپنے خیمہ میں لے
گئے اور حارث نے حلیمہ سے کہا.” مجھے ڈر ہے کہ اس لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے.پس مناسب ہے کہ تو
اسے فور آلے جا اور اس کی والدہ کے سپر د کر آ.چنانچہ حلیمہ آپ کو مکہ میں لائی اور آمنہ کے سپر دکر دیا.آمنہ نے اس جلدی کا سبب پوچھا اور اصرار کیا تو حلیمہ نے انہیں یہ سارا قصہ سُنا دیا اور یہ ڈر ظاہر کیا کہ
شاید یہ لڑکا کسی جن وغیرہ کے اثر کے نیچے آ گیا ہے.آمنہ نے کہا.ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا.میرابیٹا بڑی
شان والا ہے.جب یہ حمل میں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو دُور دراز
ملکوں تک پھیل گیا ہے.اس واقعہ کی فی الجملہ تائید صحیح مسلم کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں انس بن مالک بیان
کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض بچوں کے ساتھ مل کر کھیل رہے تھے
آپ کے پاس جبرائیل آئے اور آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ چاک کر دیا اور پھر آپ کے سینہ کے
اندر سے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ کمزوریوں کی
آلائش تھی جو اب تم سے جدا کر دی گئی ہے.اس کے بعد جبرائیل نے آپ کے دل کو مصفی پانی سے دھویا
اور سینہ میں واپس رکھ کر اسے پھر جوڑ دیا.جب بچوں نے جبرائیل کو آپ کو زمین پر گراتے اور سینہ چاک
کرتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑے ہوئے آپ کی دائی کے پاس گئے اور کہا کہ محمد کوکسی نے قتل کر دیا
ہے.جب یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو فرشتہ غائب تھا اور آپ ایک خوفزدہ حالت
میں کھڑے تھے یہ صحیح مسلم کی تصدیق کے بعد ابن ہشام کی روایت کو ایک ایسی تقویت حاصل ہو جاتی ہے
کہ بلا کسی قوی دلیل کے ہم اسے کمزور کہہ کر رد نہیں کر سکتے.مگر ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ایک کشفی نظارہ تھا.چنانچہ
لے : اس جگہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ حلیمہ اور حارث نے وہاں کوئی خون بہا ہوانہیں پایا اور نہ شق صدر کی کوئی اور
علامت دیکھی اور نہ ہی کوئی باہر پھینکی ہوئی چیز انہیں نظر آئی.: یعنی یہ کسی جن وغیرہ کے اثر کے نیچے آ گیا ہے.: مسلم جلد ا باب الاسراء
۵ : بعض ناظرین شاید کشف کی اصطلاح سے واقف نہ ہوں ، اس لیے ان کی واقفیت کی غرض سے لکھا جاتا ہے
کہ جس طرح انسان کو رات کے وقت سوتے ہوئے کوئی نظارہ دکھایا جاتا ہے جسے وہ اُس وقت اصلی سمجھتا ہے
حالانکہ وہ دراصل خواب ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات ایسے نظارے خدا کے خاص بندوں کو بیداری کی حالت
: ابن ہشام
Page 124
1+9
شق صدر کی ظاہری علامات کا مفقود ہونا یعنی اس وقت آپ کی دائی وغیرہ کو اُس کی کسی ظاہری علامات کا
نظر نہ آنا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک کشف تھا جس کا دائرہ دوسرے بچوں تک بھی وسیع ہو گیا اور جیسا
کہ خود اس کشف کے اندر یہ تصریح ہے اس سے مراد یہ تھی کہ خدائی فرشتہ نے متمثل ہو کر عالم کشف میں
آپ کا سینہ چاک کیا اور تمام کمزوریوں کی آلائش آپ کے اندر سے نکال دی.احادیث صحیحہ سے ثابت
ہے کہ معراج کی رات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی قسم کے شق صدر کا واقعہ ہوا اور فرشتوں
نے آپ کا دل نکال کر زمزم کے مصفا پانی سے دھویا اور پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا.اس جگہ یہ ذکر کرنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ سرولیم میور نے اس واقعہ کا ذکر کر کے طعن کے رنگ میں
یہ ریمارک کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایک مرگی کا دورہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا.ہم کسی کی زبان کو تو
نہیں روک سکتے مگر یقیناً میور صاحب نے یہ اعتراض کرتے ہوئے پرلے درجے کے تعصب سے کام لیا
ہے.کیونکہ اول تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مرگی کا بیمار ایک کمزور دماغ والا انسان ہوتا ہے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود میر صاحب کو اقرار ہے کہ آپ بہترین قوائے جسمانی کے مالک تھے.علاوہ ازیں خود یہ روایت بھی جس کی بناء پر یہ اعتراض کیا گیا ہے اس اعتراض کا رد کرتی ہے.کیونکہ
روایات میں یہ صاف لکھا ہے کہ اس نظارہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی نے بھی دیکھا اور
اُسی نے بھاگ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ میرے قریشی بھائی کو دوسفید پوش آدمی زمین پر گرا کر اس
کا سینہ چاک کر رہے ہیں.کیا دُنیا میں کوئی مرگی ایسی بھی ہوتی ہے جس کے متعلق دوسرے لوگ اس قسم کے
نظارہ کی شہادت دیں.بے شک وہ شخص جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ خود اپنے خیال میں یہ گمان کر سکتا ہے
کہ اُسے کسی نے پکڑ کر زمین پر دے مارا ہے لیکن یہ کہ اُسے دیکھنے والے لوگ بھی اس قسم کا نظارہ دیکھیں یہ
ایک ایسی بات ہے جسے سوائے ایک متعصب انسان کے کوئی شخص زبان پر نہیں لاسکتا.بقیہ حاشیہ : - میں بھی نظر آ جاتے ہیں.یعنی عالم بیداری میں اُن پر ایک ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ
ظاہری حواس سے الگ ہو کر ( یا بعض اوقات ظاہری حواس کے ہوتے ہوئے بھی ) کوئی خاص نظارہ دیکھتے ہیں
اور ایسی حالت میں جو نظارہ وہ دیکھتے ہیں وہ اصطلاح میں کشف کہلاتا ہے.کشف میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا
ہے کہ ایک سے زیادہ آدمیوں تک اس کا اثر پہنچتا ہے.یعنی صاحب کشف کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ایسے نظارہ
میں شریک ہو جاتے ہیں.منہ
ل : بخاری باب المعراج
Page 125
11+
بہر حال جب آپ کی عمر چار سال
کی ہوئی تو حلیمہ آپ کو واپس لا کر آپ کی والدہ کے سپر د کر گئی.یہ چار سالہ خدمت حلیمہ کی کوئی معمولی خدمت نہ تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی سے چھوٹی
خدمت کو بھی فراموش نہ کرتے تھے ، چنانچہ آپ نے عمر بھر حلیمہ کی یہ خدمت یا درکھی اور ہمیشہ اس کے ساتھ
نہایت اعلیٰ سلوک کیا.چنانچہ جب ملک میں ایک دفعہ قحط پڑا اور حلیمہ مکہ میں آئی تو آپ نے اُسے
چالیس بکریاں اور ایک اونٹ عطا فرمایا.زمانہ نبوت میں وہ ایک دفعہ آئی تو آپ نے اُسے دیکھتے ہی
”میری ماں ! میری ماں !! کہتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اوپر کی چادر اتار کر اُس کے نیچے
بچھائی.پھر جب ایک جنگ ( یعنی جنگِ حُنین ) میں قبیلہ ہوازن کے ہزار ہا قیدی پکڑے ہوئے آئے تو
آپ نے اسی رشتہ کی خاطر ان سب کو رہا کر دیا اور ایک پائی بھی اُن قیدیوں کے فدیہ میں نہیں لی.اور
اپنی ایک رضاعی بہن کو جو ان قیدیوں میں آئی تھی انعام سے مالا مال کر کے واپس کیا.حلیمہ اور اس کے
خاوند حارث کے اسلام لانے کے متعلق اختلاف ہے، مگر راجح قول یہی ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہو گئے
تھے اور اسلام کی حالت میں فوت ہوئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی عبد اللہ اور بہن شیما
نے بھی اسلام پر وفات پائی.والدہ کی کفالت اور سفر میثرب جب حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لائی تو آپ
کی عمر کم و بیش چار سال کی تھی.اس کے بعد آپ اپنی والدہ کی
کفالت میں رہے.جب آپ کی عمر چھ سال کی ہوئی تو اپنے رشتہ دار بنو نجار سے ملنے کی غرض سے آمنہ
یثرب گئیں اور آپ کو بھی ساتھ لے گئیں.اُم ایمن بھی ساتھ تھی.ممکن ہے اس سفر میں آمنہ کو اپنے
مرحوم شوہر کا مزار دیکھنے کا بھی خیال ہو.بہر حال وہ میٹر ب گئیں اور وہاں تقریباً ایک مہینہ تک قیام کیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمانہ آخر عمر تک یادر ہا.قریباً پچاس سال کے بعد جب آپ ہجرت کر کے
مدینہ گئے تو آپ نے صحابہ کو وہ مکان بتایا جہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ ٹھہرے تھے اور وہ جگہ بتائی
جہاں آپ مدینہ کے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے اور وہ تالاب بھی دکھایا جہاں آپ نے تیر نے
کی مشق کی تھی.والدہ کی وفات قریباً ایک ماہ کے قیام کے بعد آمنہ واپس روانہ ہوئیں مگر اپنے شوہر کی طرح اُن کی
موت بھی غریب الوطنی میں ہی مقدر تھی چنانچہ راستہ میں ہی بہار ہوگئیں اور مقام
ل : ابن سعد ذكر مَنْ أَرْضَعَ رَسُولَ اللَّهِ
: ابن ہشام ابن سعد وطبری
Page 126
"
ابواء میں انتقال کیا اور یہیں دفن کی گئیں.زمانہ نبوت میں جب آپ ایک دفعہ اس مقام پر سے گذرے تو
اپنی والدہ کی قبر پر بھی تشریف لے گئے اور اُسے دیکھ کر چشم پر آب ہو گئے.صحابہ نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ بھی
رونے لگے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا.اللہ نے مجھے یہ تو اجازت دی کہ میں اپنی
والدہ کی قبر کو دیکھوں لیکن دُعا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کی والدہ کی
مغفرت نہ ہوگی.کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کیا ہوگا اور کیا
نہ ہوگا.لیکن اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور موقعوں پر فرمایا ہے
کہ جو شخص شرک کی حالت میں فوت ہو اُس کے لئے دعا مانگنا درست نہیں ہے بلکہ اس کے معاملہ کو خدا
کے سپرد کرنا چاہئے.والدہ کی وفات ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یسم کی پوری پوری حالت میں آگئے اور چھوٹی عمر
میں وطن سے باہر عزیز واقرباء سے دُور ماں کی جدائی کا صدمہ ایسی حالت میں کہ باپ پہلے ہی گذر چکا ہو
کوئی معمولی صدمہ نہیں ، چنانچہ ان باتوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ایک گہرا اور مستقل اثر
ڈالا.بے شک آپ اللہ کی طرف سے رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث کئے گئے.مگر ظاہری اسباب کے لحاظ
سے ان باتوں کا بھی آپ کی طبیعت پر بہت اثر ہوا اور ایک حد تک یہ انہی ابتدائی صدموں کا نتیجہ تھا کہ
آپ کے اخلاق میں غرباء کی محبت اور مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی نے ایک خاص ممتاز رنگ اختیار
کیا.قرآن شریف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یشم کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:
اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاوى...فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ
یعنی کیا ہم نے تجھے یتیم پا کر پناہ نہیں دی.پس اب تیرا فرض ہے کہ تو بھی یتیموں کے
ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کرے.عبدالمطلب کی کفالت والدہ کی وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن
کے ساتھ مکہ پہنچے.یہ ام ایمن وہی ہے جو آپ کے والد کی وفات پر ایک
لونڈی کی حیثیت میں آپ کو ورثہ میں پہنچی تھی.بڑے ہو کر آپ نے اسے آزاد کر دیا تھا اور اس کے ساتھ
لے : یہ عام مؤرخین کی روایت ہے.بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آمنہ بنت وہب مکہ میں فوت ہوئی تھیں اور ان کی
قبر مکہ کی وادی جون میں ہے.واللہ اعلم
ہے : مسلم وابن ماجہ
سے : سورۃ الضحی آیت : ۷ ، ۱۰
Page 127
۱۱۲
بہت احسان کا سلوک فرماتے تھے.بعد میں ام ایمن کی شادی آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے
ساتھ ہوگئی اور اس کے بطن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے.ام ایمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے بعد تک زندہ رہی.بہر حال والدہ کی وفات کے بعد آپ ام ایمن کے ساتھ مکہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر
آپ کو عبدالمطلب نے براہ راست اپنی کفالت میں لے لیا.عبد المطلب آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے.خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُن کے ساتھ
بہت بے تکلف ہو گئے.عبدالمطلب کی عادت تھی کہ محن کعبہ میں فرش بچھا کر بیٹھا کرتے تھے اور کسی کی مجال
نہ تھی کہ اس فرش پر ان کے ساتھ بیٹھ سکے.حتی کہ عبدالمطلب کے اپنے لڑکے بھی ہٹ کر بیٹھتے تھے مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے جوش میں سیدھے عبدالمطلب کے پاس جا بیٹھتے تھے اور وہ آپ کو
دیکھ کر خوش ہوتے تھے.آپ کے چچا بعض اوقات آپ کو فرش پر بیٹھنے سے روکتے تو عبدالمطلب ان کو منع
کر دیتے اور کہتے کہ اسے تم کچھ نہ کہو.عبدالمطلب کی وفات اس محبت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دن گذر رہے تھے کہ
عبدالمطلب کو بھی پیغام اجل آ گیا جب ان کا جنازہ اُٹھا تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تھے اور روتے جاتے تھے.یہ تیسرا صدمہ تھا جو آپ کو بچپن میں اُٹھانا پڑا.اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی اور عبد المطلب کی عمر اختلاف روایات کے ساتھ اسی سال سے
لے کر ایک سو چالیس سال کی تھی.مختلف بیویوں سے عبدالمطلب کے کئی بیٹے تھے جن میں سے زیادہ معروف کے نام یہ ہیں.حارث،
زبیر، ابوطالب، ابولہب، عبداللہ، عباس اور حمزہ.ان میں ابو طالب اور عبداللہ کی ماں ایک تھی اور غالباً
اسی نسبت سے عبدالمطلب نے مرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی کفالت میں دیا اور
ان کو آپ کا خاص خیال رکھنے کی وصیت کی.چنانچہ اس وقت سے آپ اپنے چچا ابوطالب کی کفالت میں
رہنے لگے.قومی کاموں میں سے سقایہ اور رفادہ کا کام جو عبد المطلب کے پاس تھا وہ انہوں نے اپنے
زندہ لڑکوں میں سے بڑے لڑکے زبیر کے سپر د کیا.مگر چونکہ یہ کام بہت سارو پیہ چاہتا تھا اس لئے زبیر نے
اپنی طاقت سے زیادہ دیکھ کر دونوں کام ابو طالب کے سپر د کر دیئے لیکن ابو طالب بھی غریب آدمی تھے اس
لئے رفادہ کا کام بن نوفل کی طرف منتقل ہو گیا اور سقایہ کا کام ابو طالب نے بالآ خر عباس کے سُپر دکر دیا جو
ا: ابن سعد
Page 128
۱۱۳
نسبتاً ایک امیر آدمی تھے.اس موقع پر یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ عبدالمطلب کی زندگی تک تو بنو ہاشم نہایت معزز ومکرم تھے اور گویا
تمام قبائل قریش میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے لیکن ان کی وفات کے بعد بنو ہاشم میں سے کوئی ایسا شخص نہ نکلا
جو اس اعزاز کو قائم رکھ سکے اس لیے قریش کی عام سرداری ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بنو ہاشم کے رقیب
بنوامیہ آہستہ آہستہ بہت زور پکڑ گئے.ابوطالب کی کفالت ابو طالب نے اپنے والد کی وصیت پر نہایت دیانت اور خوبی سے عمل کیا اور
اپنے بچوں سے بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھا.ہر وقت اپنی
آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے اور رات کے وقت بھی عموماً اپنے ساتھ ہی سلاتے تھے.جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو ابو طالب کو ایک تجارتی قافلہ
سفر شام اور واقعہ بحیرا راہب
کے ساتھ شام کا سفر پیش آ گیا.چونکہ سفر لمبا اور کٹھن تھا اس لیے
انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کو مکہ ہی میں چھوڑ جائیں.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی جدائی
نہایت شاق
تھی.چنانچہ روانگی کے وقت جوش محبت میں آپ ابو طالب سے لپٹ گئے اور رونے لگے.یہ
حالت دیکھ کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے.شام کے جنوب میں بھر کی ایک مشہور مقام ہے، وہاں پہنچے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا.وہاں ایک
عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بھیرا تھا.جب قریش کا قافلہ اُس کی خانقاہ کے پاس پہنچا تو اس راہب
نے دیکھا کہ تمام پتھر اور درخت وغیرہ یکلخت سجدہ میں گر گئے.اُسے معلوم تھا کہ الہی نوشتوں کی رُو
سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اس لیے اُس نے اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ اس قافلے میں وہی نبی
موجود ہو گا.چنانچہ اُس نے اپنے قیافہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اس سے ابو طالب کو
اطلاع دی اور ابو طالب کو نصیحت کی کہ آپ کو اہلِ کتاب کے شر سے محفوظ رکھیں.علیم روایت کی رُو سے اس واقعہ کی سند کمزور ہے لیکن اگر فی الحقیقت ایسا واقعہ گذرا ہو تو کچھ تعجب بھی
نہیں.درختوں وغیرہ کا سجدہ کرنا راہب کا ایک کشفی نظارہ سمجھا جائے گا جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
مقام کے لحاظ سے کوئی غیر معمولی بات نہیں.کیا اسلام مسیحیت سے متاثر ہوا ہے؟ اس جگہ یہ ذکر ضروری ہے کہ میور صاحب اور بعض
دوسرے غیر مسلم مؤرخین نے بحیرا راہب کے واقعہ اور
Page 129
۱۱۴
اسی قسم کے دوسرے واقعات سے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سے پہلے کسی عیسائی سے ملنا
بیان ہوا ہے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعوی مسیحیت سے متاثر ہو کر کیا تھا
اور آپ کی تعلیم اسی اثر کا نتیجہ تھی.مگر یہ خیال بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے اور جس شخص کو آپ کی تعلیم اور
سوانح کا تھوڑا بہت بھی مطالعہ ہے اور تعصب نے اُس کی آنکھ پر پر دہ نہیں ڈال رکھا وہ اس اعتراض سے
کبھی دھوکا نہیں کھا سکتا.بے شک یہ درست ہے کہ ہر ذی عقل انسان اپنی استعداد کے مطابق اپنے ماحول
کا مطالعہ کرتا ہے اور ماحول کے حسن و قبیح کے نتیجہ میں اچھے یا بُرے تاثرات کا قائم ہونا بھی ایک فطری امر
ہے.پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی عیسائی کے ساتھ بعثت سے پہلے ملے ہوں گے اور آپ کو
عیسائیت کی تعلیم کے سنے کا موقع میسر آیا ہوگا تو طبعاً آپ کے دل میں اس کے اچھے اور بُرے حصوں کے
متعلق تاثرات بھی پیدا ہوئے ہوں گے.مگر یہ خیال قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے کہ آپ کی نبوت اور تعلیم ان
تاثرات کا نتیجہ تھی.کیونکہ اول تو بعثت سے پہلے آپ کا کسی عیسائی سے ایسے حالات میں ملنا ثابت نہیں کہ
جس کے متعلق یہ سمجھا جا سکے کہ اُس نے آپ کی طبیعت پر کوئی گہرا اور مستقل اثر چھوڑا ہو.لیکن اگر بالفرض
اس قسم کا کوئی اثر تھا بھی تو یقینا وہ کوئی اچھا اثر نہیں تھا کیونکہ جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ آپ کی لائی ہوئی
تعلیم میں عیسائیت کے اکثر اصولی مسائل سے شدید اختلاف پایا جاتا ہے مثلاً موجود الوقت عیسائی مذہب
کی بنیادزیادہ تر اُلوہیت مسیح ، تثلیث اور کفارہ کے عقائد پر ہے.مگر ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ قرآن شریف
میں ان تینوں مسائل کے خلاف نہایت سختی سے اظہارِ خیال کیا گیا ہے.حتی کہ مسیح کی مزعومہ خدائی اور
ابنیت کے متعلق یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ قریب ہے کہ اس سے زمین و آسمان
پھٹ جائیں.اندریں حالات اسلام کی تعلیم کو عیسائیت کی طرف منسوب کرنا ایک مجنونانہ کوشش سے زیادہ
حیثیت نہیں رکھتا.باقی رہا یہ امر کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح ناصری کی تعریف کی گئی ہے سو اس سے بھی مندرجہ بالا
اعتراض کی تائید میں کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی.کیونکہ اول تو حضرت مسیح کی جو تعریف کی گئی ہے وہ بطور
ایک نبی کے ہے نہ کہ بطور ابن اللہ یا خدا ہونے کے جو عیسائی مذہب کا دعوی ہے.دوسرے یہ تعریف
حضرت مسیح کے ساتھ خاص نہیں ہے.کیونکہ قرآن شریف نے سارے گذشتہ انبیاء کی تعریف کی ہے اور
انہیں نہایت بزرگ اور قابلِ احترام ہستیاں قرار دیا ہے بلکہ قرآن شریف نے بڑے زور کے ساتھ اس
: سورۃ مریم آیت ۹۱ تا ۹۳
Page 130
۱۱۵
اصول کو پیش کیا ہے کہ دُنیا کی ساری قوموں میں خدا کے رسول گزرے ہیں.اور اس طرح اُس نے
مسلمانوں کے دلوں میں تمام اقوامِ عالم کے بزرگوں کی عزت قائم کر دی ہے مگر یہ ایک بین حقیقت ہے کہ
حضرت مسیح کی خدائیت اور عیسائی مذہب کے دوسرے اصولی عقائد کو اسلام نے نہایت سختی کے ساتھ
رڈ کیا ہے اور حضرت مسیح کو ایک انسان رسول سے زیادہ حیثیت نہیں دی جو اپنی زندگی کے دن گزار
کر دوسرے رسُولوں کی طرح وفات پاگئے پس مسیحی مذہب سے متأثر ہونے کا اعتراض بالکل غلط اور
باطل ہے.اور اگر یہ کہا جائے کہ مسیحی مذہب کی بعض دینی اور اخلاقی تعلیمات اسلام میں بھی پائی جاتی ہیں جس
سے یہ خیال ہوسکتا ہے کہ اسلام نے ان تعلیمات کو مسیحیت سے اخذ کیا ہے تو یہ بھی ایک فضول اعتراض ہوگا
کیونکہ اول تو جب کہ اسلام اور موجود الوقت مسیحیت کی بہت سی اصولی تعلیمات ایک دوسرے سے بالکل
جدا ہیں تو کسی ضمنی حصہ میں ان دو تعلیموں کا آپس میں متشابہ ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں سمجھا جا سکتا
کہ ایک تعلیم دوسرے سے ماخوذ ہے.دوسرے جب کہ اسلام حضرت مسیح کو خدا کا ایک برگزیدہ رسول
قرار دیتا ہے اور خود بھی خدا کی طرف سے ہونے کا مدعی ہے تو یہ لازمی تھا کہ بوجہ ایک ہی منبع سے نکلی
ہوئی چیزیں ہونے کے اسلام اور مسیحیت کی بعض تعلیمیں ایک دوسرے کے متشابہ ہوتیں.کیونکہ بہر حال
ہدایت کے اصول ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے ایک ہی ہیں.تیسرے قرآن شریف خود اس بات کا مدعی
ہے کہ اس نے سب گذشتہ تعلیموں کی دائی صداقتوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے.جیسا کہ فرماتا ہے
فيهَا كُتُبْ قَيْمَةٌ " یعنی قرآن کے اندر تمام گذشتہ صحف کی پختہ اور مستقل باتیں جمع کر دی گئی ہیں.پس اس جہت سے بھی مسیحیت کی کوئی خصوصیت ثابت نہیں ہوتی..اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ قرآن شریف نے اپنے اس خاصہ کو کہ اس میں گذشتہ تعلیمات کی
سب دائمی صداقتیں اور پختہ اور مستقل باتیں شامل کر دی گئی ہیں ایک کمال کے رنگ میں پیش کیا ہے اور
اس پہلو سے اسے گویا ایک شہد کی مکھی سے تشبیہ دی ہے.جو ہر قسم کے پھل اور پھول سے اُس کا جو ہر لے
کر باریک در بار یک کیمیائی رنگ میں ایک نہایت لطیف چیز تیار کر دیتی ہے جو باوجود مختلف پھلوں اور
پھولوں کا جو ہر ہونے کے ایک بالکل ہی نئی چیز ہوتی ہے جسے کسی خاص پھل یا پھول کی طرف منسوب نہیں
کیا جا سکتا.علاوہ ازیں قرآن شریف نے صرف گذشتہ صحف ہی سے اُن کی پختہ تعلیمات کو اخذ نہیں کیا
ا : سورة فاطر: ۲۴
: سورة مینه آیت : ۴
۳ : سورۃ نحل آیت : ۶۹
Page 131
بلکہ چونکہ وہ ایک دائمی شریعت کا حامل ہے اس لئے اس نے قیامت تک کی ضروریات کے پیش نظر بہت سی
نئی باتوں کو بھی زائد کر کے ایک کامل اور ابدی شریعت پیش کی ہے اور خدا کی طرف سے اس میں ایسے
خواص ودیعت کر دیئے گئے ہیں کہ اس ظاہری عالم کی طرح وہ قیامت تک کے لئے بنی نوع انسان کی دینی
ضروریات کا سامان اپنے اندر مخفی رکھتا ہے جو سب ضرورت ظاہر ہوتا رہتا ہے.دراصل قرآن شریف
مندرجہ ذیل تعلیمات کا مجموعہ ہے:
اول گذشتہ صحف کے وہ حصے جو ایک دائمی اور عالمگیر شریعت کا جزو بن سکتے تھے.دوم آئندہ کے لئے مختلف اقوامِ عالم کی ضروریات کے مناسب حال مستقل تعلیم جو حقوق العباد اور
حقوق اللہ کی کامل ادا ئیگی اور ہر قسم کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے لئے قیامت تک کے لئے ضروری تھی.بہر حال یہ خیال کہ قرآن شریف یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مسیحیت یا کسی اور مذہب کی
تعلیم کا نتیجہ تھی، بالکل غلط اور باطل ہے اور ایسا دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہے جو اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیم
سے قطعا نا بلد ہے اور بالخصوص بحیرا راہب وغیرہ کی ملاقات کی طرف اسلامی تعلیمات کو منسوب کرنا تو
ایک بالکل ہی مضحکہ خیز بات ہے جو کسی دانا شخص کی زبان پر نہیں آ سکتی.آپ کا بکریاں چرانا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر سے واپس آئے تو بدستور
ابوطالب کے پاس ہی رہتے تھے مگر چونکہ عرب میں بچوں کو عموماً مویشی
چرانے کے کام پر لگا دیتے تھے اس لئے اس زمانہ میں آپ نے بھی کبھی کبھی یہ کام کیا اور بکریاں چرائیں.زمانہ نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ بکریاں چرانا بھی انبیاء کی سنت ہے.اور میں نے بھی بکریاں چرائی
ہیں.چنانچہ ایک موقع پر سفر میں آپ کے اصحاب جنگل میں پہلو جمع کر کے کھانے لگے تو آپ نے فرمایا.کالے کالے پیلو تلاش کر کے کھاؤ کیونکہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس وقت کا میرا تجربہ ہے کہ
کالے رنگ کے پیلو زیادہ عمدہ ہوتے ہیں کے
لے : اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کا کام بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے گلہ بانی کا رنگ رکھتا ہے.پس اللہ تعالیٰ
ان سے ان کی ابتدائی عمر میں چرواہے کا کام لے کر تصویری زبان میں یہ اشارہ کر دیتا ہے کہ اب تم انسانوں کی
گلہ بانی کے لئے بھی تیار ہو جاؤ.: بخاری کتاب بدء الخلق باب يعكفون على اصنام
Page 132
۱۱۷
بدیوں سے خدائی حفاظت اسی زمانہ کا ایک واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
رات اپنے ساتھی سے کہا جو بکریاں چرانے میں آپ کا شریک تھا کہ
تم میری بکریوں کا خیال رکھو تا کہ میں ذرا شہر جا کر لوگوں کی مجلس دیکھ آؤں.ان دنوں میں دستور تھا کہ
رات کے وقت لوگ کسی مکان میں جمع ہو کر کہانیاں سناتے اور شعر و غزل کا شغل کیا کرتے تھے اور بعض
اوقات اسی میں ساری ساری رات گزار دیتے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن کے شوق میں یہ
تماشہ دیکھنے گئے مگر اللہ تعالیٰ کو اس لغو کام میں خاتم النبیین کی شرکت پسند نہ آئی ؛ چنانچہ ایک جگہ آپ گئے
مگر راستے میں ہی نیند آ گئی اور سو گئے اور صبح تک سوتے رہے.ایک دفعہ اور آپ کو یہی خیال آیا مگر پھر
بھی دست غیبی نے روک دیا.زمانہ نبوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے ساری
عمر میں صرف دو دفعہ اس قسم کی مجلس میں شرکت کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ روک دیا گیا.حرب فجار عرب
ایک نہایت جنگجو قوم تھی اور لڑنے مرنے کو یہ لوگ فخر سمجھتے تھے.اسی لیے بات بات پر
تلوار بھی جاتی تھی اور جب کبھی ایسا موقع آتا تو ایک بڑے پیالے میں خون بھر کر سب اس
کے اندر اُنگلیاں ڈبو کر قسم کھاتے تھے کہ لڑ کر مر جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے.مختلف قبائل کی آپس میں
عداوت رہتی تھی کیونکہ ہر قبیلہ کو اپنی عزت اور بڑائی کا از بس خیال تھا.ایسی صورت میں میلوں وغیرہ میں
جہاں مختلف قسم کے لوگ جمع ہوتے ہیں لڑائی کی وجوہات پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں.چنانچہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بچپن ہی تھا تو عکاظ کے میلہ کے موقع پر جو مکہ سے جانب شرق تین دن
کی مسافت پر ایک خوشگوار وادی میں لگا کرتا تھا، قبائل قیس عیلان اور بنو کنانہ کے درمیان کچھ چھیڑ چھاڑ
شروع ہوئی.اس زمانہ میں قیس عیلان کے مختلف قبائل مکہ سے جنوب مشرق میں طائف اور مکہ کے
درمیان آباد تھے.ایک عرصہ تک تو دونوں طرف کے رؤساء نے جنگ کی نوبت آنے سے بچائے رکھا، مگر
آہستہ آہستہ تعلقات کشیدہ ہوتے گئے اور بالآ خر لڑائی تک نوبت پہنچ گئی.اس جنگ کو تاریخ میں حرب فجار
کہتے ہیں.جس کے معنے ناجائز جنگ کے ہیں.کیونکہ اس جنگ کی ابتداء شہر حرم میں ہوئی تھی جس کے اندر
لڑنا عرب کے قدیم دستور کے مطابق ممنوع تھا.غرض یہ جنگ ہوئی اور ایسے زور شور سے ہوئی کہ زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں خاص شہرت رکھتی ہے
بنو کنانہ بشمولیت قبیلہ قریش ایک طرف تھے اور قیس عیلان بشمولیت قبیلہ ہوازن دوسری طرف.اس جنگ
ا : طبری
Page 133
۱۱۸
کی سب سے خطر ناک آخری لڑائی تھی جو حرب فجار کی چوتھی لڑائی کہلاتی ہے.اس میں جوش کا یہ عالم تھا کہ
بعض سرداروں نے اپنے آپ کو رسوں سے بندھوا دیا تھا کہ اگر بھاگنا چاہیں بھی تو نہ بھاگ سکیں.دن کے شروع حصہ میں قیس عیلان کا پلہ بھاری رہا لیکن آخر میں بنو کنانہ نے دبا لیا اور قیس عیلان کی
شکست کے بعد ہر دوفریق میں صلح ہوگئی.اس لڑائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے.مگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ
نے خود قتال نہیں کیا بلکہ آپ کی شرکت صرف اس حد تک محدود تھی کہ آپ فوج میں شامل تھے اور اپنے
چاؤں کو تیر پکڑا تے جاتے تھے.اس وقت آپ کی عمر میں سال کے قریب تھی.اس لڑائی میں ہر قبیلہ
کا افسر الگ الگ تھا.چنانچہ بنو ہاشم زبیر بن عبدالمطلب کے ماتحت تھے مگر بنو کنانہ کی ساری فوج کا افسر
حرب بن امیہ تھا جو ابوسفیان کا والد اور امیر معاویہ کا دادا تھا.لے
حلف الفضول قدیم زمانہ میں عرب کے بعض شریف دل اشخاص کو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ با ہم مل کر
عہد کیا جاوے کہ ہم ہمیشہ حقدار کو اس کا حق حاصل کرنے میں مدد دیں گے اور ظالم کو
ظلم سے روکیں گے اور عربی میں چونکہ حق کو فضل بھی کہتے ہیں جس کی جمع فضول ہے، اس لئے اس معاہدہ کا
نام حلف الفضول رکھا گیا.بعض روایتوں کی رُو سے چونکہ اس تجویز کے محرک ایسے شخص تھے جن کے
ناموں میں فضل کا لفظ آتا تھا، اس لیے یہ عہد حلف الفضول کے نام سے مشہور ہو گیا.بہر حال حرب فجار
کے بعد اور غالباً اسی جنگ سے متأثر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبدالمطلب کے دل
میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اس حلف کو پھر تازہ کیا جاوے؛ چنانچہ اس کی تحریک پر بعض قبائل قریش کے
نمائندگان عبد اللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے جہاں عبداللہ بن جدعان کی طرف سے ایک دعوت کا
انتظام تھا اور پھر سب نے اتفاق کر کے باہم قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظلم کو روکیں گے اور مظلوم کی مدد کریں
گے.اس عہد میں حصہ لینے والوں میں بنو ہاشم ، بنو مطلب ، بنو اسد ، بنوزہرہ اور بنو تیم شامل تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے اور شریک معاہدہ تھے؛ چنانچہ آپ ایک دفعہ
نبوت کے زمانہ میں فرماتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسی قسم میں شریک ہوا تھا کہ
اگر آج اسلام کے زمانہ میں بھی مجھے کوئی اس کی طرف بلائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا اور شاید اسی خیال
: روض الانف مصنفہ امام سہیلی جلد اصفهاا
ل : ابن ہشام
سے : یادر رکھنے کا مقام ہے کہ بنونوفل اور بنوامیہ اس موقع پر بھی بنو ہاشم سے الگ رہے.
Page 134
119
کا اثر تھا کہ جب ایک دفعہ امیر معاویہ کے زمانہ میں اُن کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابوسفیان نے جو اس وقت
مدینہ کے امیر تھے حضرت حسین بن علی بن ابی طالب کا کوئی حق دبا لیا تو حضرت حسین نے کہا کہ ” خدا کی قسم
اگر ولید نے میرا حق نہ دیا تو میں تلوار نکال کر مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کی طرف
لوگوں کو بلاؤں گا.جس وقت عبداللہ بن زبیر نے یہ سنا تو کہا کہ اگر حسین نے اس قسم کی طرف بلایا تو میں
اس پر ضرور لبیک کہوں گا اور ہم یا تو اس کا حق دلوائیں گے اور یا اس کوشش میں سب مارے جائیں گے.بعض اور آدمیوں نے بھی اسی قسم کے الفاظ کہے جس پر ولید آب گیا اور اس نے حضرت حسین کا حق ادا کر
دیا.یہ خیال رہے کہ عبداللہ بن زبیر بنو اسد میں سے تھے جو حلف الفضول میں شریک تھے.حلیہ مبارک اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے اور جسمانی نشو ونما مکمل ہو چکا تھا.اس لیے
اس موقع پر آپ کا حلیہ بیان کر دینا مناسب ہوگا.لکھا ہے کہ آپ میانہ قد تھے.رنگ
بہت خوبصورت تھا یعنی نہ تو بہت ہی سفید جو بُرا لگے اور نہ ہی گندم گوں بلکہ گندم گوں سے کچھ سفید تھا.سر کے بال بالکل سیدھے نوکدار نہ تھے بلکہ کسی قد رخدار تھے.داڑھی گھنی اور خوبصورت تھی.جسم درمیانہ تھا.جلد نازک اور ملائم تھی اور آپ کے جسم اور پسینہ میں ایک قسم کی خوشبو پائی جاتی تھی.سر بڑا تھا.سینہ فراخ.ہاتھ پاؤں بھرے بھرے.ہتھیلیاں چوڑی.چہرہ گول.پیشانی اور ناک اونچی.آنکھیں سیاہ اور روشن اور
پلکیں دراز تھیں.چلنے میں وقار تھا.مگر عموما تیزی کے ساتھ قدم اٹھا تھا.گفتگو میں آہنگی ہوتی تھی حتی کہ
اگر سننے والا چاہے تو آپ کے الفاظ کو گن سکتا تھا.ناراضگی کے وقت چہرہ سُرخ ہو جاتا تھا اور خوشی کے
موقع پر بھی چمک اُٹھتا تھا.انگلستان کا مشہور مؤرخ سرولیم میور آپ کا حلیہ بیان کر کے لکھتا ہے کہ :
' آپ کا سردارانہ رنگ ڈھنگ ایک اجنبی شخص کے دل میں کچھ رُعب پیدا کر دیتا تھا جو
الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا لیکن جب اُسے آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا اور وہ
آپ سے واقف ہو جاتا تھا تو اس کے دل میں بجائے ڈر اور خوف کے عقیدت اور محبت کے
جذبات پیدا ہونے لگتے تھے.‘۳
مشاغل تجارت جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب جوان تھے اور کاروبار
زندگی میں مصروف ہونے کا وقت آ گیا تھا اور چونکہ ابو طالب کی مالی حالت بھی
اچھی نہیں تھی اس لیے بھی اس بات کی ضرورت تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مناسب کام شروع
لی : ابن ہشام
: بخاری کتاب صفته النبی و شمائل ترمذی ۳ : میور صفحه ۲۵
Page 135
۱۲۰
کر کے اُن کے بوجھ کو ہلکا کریں؛ چنانچہ ابو طالب کی خواہش اور تحریک پر آپ نے تجارت کا کام شروع
فرما دیا.مکہ سے تجارت کے قافلے مختلف علاقوں کی طرف جاتے تھے.جنوب میں یمن اور شمال میں شام کی
طرف تو با قاعدہ تجارت کا سلسلہ جاری تھا.اس کے علاوہ بحرین وغیرہ کے ساتھ بھی تجارت تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان سب ملکوں میں تجارت کی غرض سے گئے.اور ہر دفعہ نہایت دیانت و
امانت اور خوش اسلوبی اور ہنر مندی کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کیا.مکہ میں بھی جن لوگوں کے ساتھ آپ کا
معاملہ پڑا وہ سب آپ کی تعریف میں رطب اللسان تھے ؛ چنانچہ سائب ایک صحابی تھے.وہ جب اسلام
لائے تو بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کی.آپ نے فرمایا.میں
ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں.سائب نے عرض کی.”ہاں یا رسول
اللہ ! آپ پر میرے ماں باپ قربان
ہوں.آپ ایک دفعہ تجارت میں میرے شریک تھے اور آپ نے ہمیشہ نہایت صاف معاملہ رکھا.عبد اللہ بن ابی الحمساء ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے ایک دفعہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کیا اور میرے ذمہ آپ کا کچھ حساب باقی رہ گیا.جس پر
میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں اسی جگہ ٹھہریں میں ابھی آتا ہوں.مگر مجھے بھول گیا اور تین دن کے
بعد یاد آیا اس وقت جب میں اس طرف گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے.مگر آپ نے
سوائے اس کے مجھے کچھ نہیں کہا کہ تم نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے.میں یہاں تین دن سے تمہارے
انتظار میں ہوں.‘ اس سے غالباً یہ مراد نہیں کہ آپ مسلسل تین دن تک اسی جگہ ٹھہرے رہے بلکہ منشا
یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مناسب اوقات میں کئی کئی دفعہ اس جگہ جا کر دیر دیر تک عبداللہ کا انتظار فرماتے
ہوں گے تاکہ عبد اللہ کو آپ کی تلاش کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو.اسی قسم کے واقعات سے مکہ والوں میں آپ کا نام امین مشہور ہو گیا تھا اور آپ کی دیانت اور
امانت کی وجہ سے سب لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور آپ کو نہایت راستباز اور صادق القول
یقین کرتے تھے.تجارتی کاروبار کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال کے قریب
ل : نور النبراس اور مسند منبل بحوالہ سیرۃ النبی
: ابوداؤد جلد ۲ صفحه ۳۳۴
: ابو داؤد جلد ۲ صفحہ ۳۱۷
: ابن ہشام
Page 136
۱۲۱
ہوئی تو خدیجہ بنت خویلد نے جو قبیلہ بنو اسد کی ایک نہایت شریف اور مالدار خاتون تھی اور مکہ کی تجارت
میں اس کا بہت بڑا حصہ تھا آپ کو تجارتی مال دے کر شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجا اور اپنے غلام
میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا.اس سفر میں آپ کی محنت اور برکت اور دیانتداری کے طفیل اللہ تعالیٰ کے
فضل سے بہت نفع ہوا اور آپ نہایت کامیاب ہو کر واپس آئے.اسی طرح آپ نے دو تین تجارتی سفر
دُوسرے علاقوں کی طرف بھی کئے.حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی حضرت خدیجہ ایک بیوہ اور صاحب اولا دعورت تھیں اور یکے
بعد دیگرے دو خاوند کر چکی تھیں.مگر دونوں فوت ہو چکے تھے.چونکہ نہایت معزز اور دولتمند اور شریف تھیں حتی کہ اُن کی شرافت کی وجہ سے اُن کا نام طاہرہ مشہور ہو گیا
تھا.اس لئے مکہ کے کئی لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، مگر انہوں نے سب کا انکار کیا.اب جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ پڑا اور اُنہوں نے آپ کے اخلاق فاضلہ اور قابلیت کو
دیکھا اور اپنے خادم میسرہ کو بھی آپ کی تعریف میں رطب اللسان پایا تو انہوں نے خود آپ کو
نکاح کا پیغام بھیجا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے مشورہ کے بعد قبول کر لیا؛ چنانچہ آپ
کے رشتہ دار اور خدیجہ کے قریبی رشتہ دار جمع ہوئے اور ابو طالب نے پانسو درہم مہر پر خدیجہ کے ساتھ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھ دیا.اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچھپیں سال کی تھی
اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال کی تھی.گویا خدیجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ سال بڑی
تھیں.اس نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد فوت ہو چکے تھے.اس لیے خدیجہ کی طرف
سے ان کے چچا عمرو بن اسد نے شرکت کی ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی وہ سب
سوائے ابراہیم کے جو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری
عمر میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے ، خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی؛ چنانچہ حضرت خدیجہ سے آپ
کے تین لڑکے اور چار لڑکیاں ہوئے.لڑکوں کے نام قاسم ، طاہر اور طیب تھے.بعض روایتوں میں ایک
چوتھا بیٹا عبد اللہ بھی بیان ہوا ہے مگر عام خیال یہ ہے کہ طیب کا دوسرا نام عبداللہ تھا.لڑکیوں کے نام زینب،
رقیہ ، ام کلثوم اور فاطمہ تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی
: زرقانی
: ابن سعد و روض الانف جلد اصفحه ۱۲۲
Page 137
۱۲۲
آپ کے دعویٰ نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم آپ کے
بڑے بیٹے قاسم کے نام پر تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولا دسب بچپن میں ہی فوت ہوگئی.مگر لڑکیاں سب بڑی ہوئیں
اور اسلام لائیں ، لیکن سوائے چھوٹی لڑکی فاطمتہ الزہرا کے باقی کسی لڑکی کی نسل نہیں چلی.بڑی لڑکی
زینب ابوالعاص بن ربیع کے ساتھ بیاہی گئیں جو حضرت خدیجہ کے عزیزوں میں سے تھے.ابوالعاص کے
ہاں زینب کے بطن سے ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئے.لڑکا تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا ،مگرلڈ کی
بڑی ہوئی اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کے عقد میں آئی ، مگر اس کی نسل نہیں چلی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو بہت عزیز رکھتے تھے.ابو العاص ہجرت کے کئی سال بعد تک اسلام نہیں
لائے.جس کی وجہ سے زینب کو بھی بعض تکالیف کا سامنا کرنا پڑا.زینب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی میں ہی فوت ہو گئیں.رقیہ اور اُم کلثوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چا ابولہب کے دولڑکوں متنبہ اور عتیبہ کے عقد
میں آئیں مگر اسلام کے زمانہ میں جب ابولہب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی تو پیشتر
اس کے کہ رخصتانہ ہوتا یہ دونوں نکاح فسخ ہو گئے.اس کے بعد رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت
عثمان بن عفان کے نکاح میں آئیں ، جس کی وجہ سے اُن کو ذوالنورین یعنی دونو روں والا کہتے ہیں مگر
ان دونوں کی نسل نہیں چلی.یعنی رقیہ کے بطن سے تو ایک لڑکا عبد اللہ پیدا ہوکر فوت ہو گیا اور ام کلثوم کے
کوئی اولا دہی نہیں ہوئی.رقیہ کا جنگ بدر کے زمانہ میں اور ام کلثوم کا فتح مکہ کے بعد انتقال ہو گیا.سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ تھیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھیں.یہ ہجرت کے بعد حضرت علیؓ کے عقد میں آئیں اور انہی کے بطن سے حضرت امام حسن اور حسین پیدا ہوئے جن
کی اولا دستید کہلاتی ہے.حضرت فاطمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چھ ماہ بعد فوت ہوئیں یا
حضرت خدیجہ کی اولاد جو اُن کے پہلے دو خاوندوں سے تھی وہ دولڑکوں ہند اور ہالہ اور ایک لڑکی ھند
پر مشتمل تھی جو خدا کے فضل سے سب مسلمان ہو گئے تھے.کعبہ کی جدید تعمیر تعمیر کعبہ کا واقعہ باب دوم میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے چونکہ
کعبہ کی عمارت کو کسی وجہ سے نقصان پہنچ گیا تھا ، اس لیے قریش نے اسے گرا کر پھر.لے : ابن ہشام وابن سعد وزرقانی
Page 138
۱۲۳
از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا مگر گرانے کا کام شروع کرنے سے سب ڈرتے تھے کہ خدا کا گھر ہے کوئی آفت نہ
آجاوے.آخر ولید بن مغیرہ نے جو معمر اور سرداران قریش میں سے تھا اس کام کو شروع کیا اور جب لوگوں
نے ایک رات انتظار کر کے دیکھ لیا کہ ولید پر اس وجہ سے کوئی آفت نہیں آئی تو پھر سب شامل ہو گئے جب
پُرانی عمارت کو گراتے گراتے حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر پہنچے تو رک گئے اور اُن کے اُوپر نئی تعمیر شروع
کی.اتفاق ایسا ہوا کہ ساحل کے پاس ایک بڑی کشتی ٹوٹ
گئی تھی.اس کی لکڑی قریش نے خرید لی لیکن چونکہ
یہ لکڑی ساری چھت کے لیے ناکافی تھی.اس واسطے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے قریش کعبہ کی اس جدید
تعمیر کو ابراہیم خلیل اللہ کی بنیادوں پر کھڑا نہیں کر سکے، بلکہ ایک طرف سات ہاتھ جگہ چھوڑ دی.بعض اور
تبدیلیاں بھی قریش نے کیں مگر ان کا بیان او پر گذر چکا ہے اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں.جب قریش کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود کی جگہ پر پہنچے تو قبائلِ قریش کے اندر اس بات پر سخت
جھگڑا ہوا کہ کون قبیلہ اسے اس کی جگہ پر رکھے.ہر قبیلہ اس عزت کو اپنے لیے چاہتا تھا.حتی کہ لوگ آپس
میں لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے اور بعض نے تو زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق ایک خون سے بھرے
ہوئے پیالے میں اُنگلیاں ڈبو کر قسمیں کھائیں کہ لڑ کر مر جائیں گے مگر اس عزت کو اپنے قبیلہ سے باہر نہ
جانے دیں گے.اس جھگڑے کی وجہ سے
تعمیر کا کام کئی دن تک بند رہا.آخر ابو امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش
کی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم کے اندر آتا دکھائی دے وہ اس بات میں حکم ہو کر فیصلہ کرے کہ اس موقع
پر کیا کرنا چاہئے.اللہ کی قدرت لوگوں کی آنکھیں جو اٹھیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
لا رہے ہیں.آپ کو دیکھ کر سب پکا راُٹھے.امین امین.اور سب نے با تفاق کہا کہ ”ہم اس کے فیصلہ
پر راضی ہیں.جب آپ قریب آئے تو انہوں نے آپ سے حقیقت امر بیان کی اور فیصلہ چاہا.آپ
نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ایسا فیصلہ فرمایا کہ سب سردارانِ قریش دنگ رہ گئے اور آفرین پکار اُٹھے.آپ نے اپنی چادر لی اور اس پر حجر اسود کو رکھ دیا اور تمام قبائل قریش کے رؤساء کو اس چادر کے کونے
پکڑ وادیئے اور چادر اُٹھانے کا حکم دیا.چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اُٹھایا اور کسی کو بھی شکایت نہ رہی.یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویری زبان میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل جواب
برسر پیکار ہیں وہ اس پاک وجود کے ذریعہ سے ایک مرکز پر جمع ہو جائیں گے.جب حجر اسود کی اصلی جگہ
کے محاذ میں چادر پہنچی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اُسے چادر پر سے اُٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا ہے
ل : طبری وابن ہشام وابن سعد وزرقانی و تاریخ خمیس
66
Page 139
۱۲۴
یہ جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا تصویری زبان میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عنقریب نبوت کی عمارت کے
کونے کا پتھر آپ کے وجود سے اپنی جگہ پر قائم ہو گا لے
عام مؤرخین کعبہ کی اس تعمیر کی تاریخ کے متعلق صرف اتنا لکھ دیتے ہیں کہ یہ آپ کی پینتیس سال کی
عمر کا واقعہ ہے حالانکہ اگر اس زمانہ کے حالات کو مد نظر رکھ کر دیکھا جاوے تو دراصل نئی عمارت کے واسطے
سامان جمع کرنے اور پرانی عمارت کو گرانے وغیرہ کا کام ایک کافی لمبا وقت چاہتا تھا.لہذا قرین قیاس یہ
ہے کہ اس کام کی تیاری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں ہی شروع ہو گئی تھی اور نئی عمارت
کے واسطے سامان یعنی پتھر لکڑی وغیرہ آہستہ آہستہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا؛ چنانچہ ایک صحیح روایت آتی ہے
کہ ایک دفعہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کعبہ کے واسطے پتھر اٹھا اٹھا کر جمع کر رہے تھے تو آپ کے
چچا عباس نے آپ سے کہا.بھتیجے اپنا نہ بند اپنے شانہ پر رکھ لو تا کہ پتھروں کی رگڑ وغیرہ نہ لگے.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیل حکم تو کی مگر چونکہ اس سے آپ کے جسم کا کچھ ستر والا حصہ نگا ہو گیا.آپ شرم
کے مارے زمین پر گر گئے اور آپ کی آنکھیں پتھرا گئیں اور آپ بے تاب ہوکر میراتہ بند میرا نہ بند
پکارنے لگ گئے.حتی کہ پھر آپ نے جلدی سے اپنا تہ بند درست کر لیا.یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جوصرف
ابتدائی عمر کی طرف ہی منسوب ہو سکتا ہے؛ چنانچہ بعض گذشتہ مؤرخین نے بھی لکھا ہے کہ یہ صغرسنی کا واقعہ
ہے.ہاں حجر اسود کے متعلق حکم بن کر فیصلہ کرنے کا واقعہ بے شک بعد کا ہے.کیونکہ اس کے متعلق یہ
روایت ہے کہ آپ کو آتا دیکھ کر سب لوگ امین امین پکا راٹھے تھے اور ظاہر ہے کہ امین کا لقب آپ نے
اس وقت پایا جب معاملات میں پڑ کر آپ کی امانت و دیانت روز روشن کی طرح ظاہر ہو کر مسلم ہوگئی.زید بن حارثہ کا آپ کی خدمت میں آنا حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے جن کا نام حکیم
بن حزام تھا.یہ بڑے تاجر آدمی تھے اور ہمیشہ
تجارتی قافلوں کے ساتھ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے تھے.ایک دفعہ یہ کہیں تجارت کے لیے گئے تو چند
ایک غلام خرید کر لائے اور اُن میں سے ایک غلام اپنی پھوپھی کی نذر کیا.اُس کا نام زید بن حارثہ تھا.زید
دراصل ایک آزاد خاندان کا لڑکا تھا مگر کسی لوٹ مار میں قید ہو کر غلام بنا لیا گیا تھا.خدیجہ نے زید کو ایک
ہوشیار اور ہونہارلڑ کا پاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر د کر دیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ دستور تھا کہ اپنے غلاموں اور خادموں کو نہایت محبت اور پیار
ا : زبور ۱۸ آیت ۲۲
: بخاری باب بنیان الکعبه سے : ابن ہشام وزرقانی و سہیلی
Page 140
۱۲۵
کے ساتھ رکھتے تھے اور اُن سے اپنے رشتہ داروں کی طرح سلوک کرتے تھے ؛ چنانچہ زید کے ساتھ بھی
آپ کو محبت تھی اور زید چونکہ ایک وفادار دل رکھتا تھا، اس لئے اُسے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
بہت ارادت ہو گئی.اُسی زمانہ میں زید کا باپ حارثہ اور اس کا چچا کعب زید کا پتہ لیتے لیتے مکہ آ نکلے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عاجزی سے استدعا کی کہ زید کورہا کر کے
اُن کے ساتھ بھیج دیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہاں اگر زید جانا چا ہے تو میری طرف سے
بخوشی اجازت ہے.اس پر زید کو بلایا گیا اور آپ نے اُسے کہا.” زید تم ان کو پہچانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟“
اُس نے عرض کی.”ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں.آپ نے فرمایا.” یہ تم کو لینے آئے
ہیں.اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے تم کو بخوشی اجازت ہے.“ زید نے جواب دیا.”میں آپ کو
چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا.آپ میرے لیے میرے چا اور باپ سے بڑھ کر ہیں.زید کا باپ غصہ میں
بولا.” ہیں ! تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا.”ہاں! کیونکہ میں نے ان میں ایسی خوبیاں
دیکھی ہیں کہ اب میں کسی کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کا یہ جواب سنا تو فوراً اُٹھ کھڑے ہوئے اور زید کو خانہ کعبہ
کے پاس لے جا کر بلند آواز سے فرمایا.”لوگو! گواہ رہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا اور اسے اپنا بیٹا بنا تا
ہوں.یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا.زید کے والد اور چچا نے یہ نظارہ دیکھا تو حیران
رہ گئے اور زید کو بخوشی آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے.اُس دن سے زید بجائے زید بن حارثہ کے زید بن محمد
کہلانے لگے.لیکن ہجرت کے بعد جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم اترا کہ مُنہ بولا بیٹا بنانا جائز
نہیں ہے تو زید کو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور پیار اس
وفادار خادم کے ساتھ وہی رہا جو پہلے تھا، بلکہ دن بدن ترقی کرتا گیا اور زید کی وفات کے بعد زید کے لڑکے
اسامہ بن زید سے بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام ایمن کے بطن سے تھے آپ کا وہی
سلوک اور وہی پیار تھا.زید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے صرف انہی کا نام قرآن شریف
میں صراحت کے ساتھ مذکور ہوا ہے.ل: اسد الغابه وابن ہشام
۳ : سورۃ احزاب: ۳۸
:
سورۃ احزاب : ۶۰۵
Page 141
۱۲۶
علی بن ابی طالب کا آنحضرت کے گھر آنا ابوطالب ایک بہت باعزت آدمی تھے مگر غریب
تھے اور بڑی تنگی سے اُن کا گزارہ چلتا تھا.خصوصاً
ان ایام میں جب کہ ملکہ میں ایک قحط کی صورت تھی اُن کے دن بہت ہی تکلیف میں کٹتے تھے.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چا کی اس تکلیف کو دیکھا تو اپنے دوسرے چچا عباس سے ایک دن فرمانے
گے چا! آپ کے بھائی ابوطالب کی معیشت تنگ ہے.کیا اچھا ہو کہ اُن کے بیٹوں میں سے ایک کو آپ
اپنے گھر لے جائیں اور ایک کو میں لے آؤں.عباس نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر دونوں مل کر
ابوطالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ درخواست پیش کی.اُن
کو اپنی اولاد میں عقیل سے بہت محبت
تھی.کہنے لگے عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ؛ چنانچہ جعفر کو
عباس اپنے گھر لے آئے اور علی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لے آئے.حضرت علیؓ کی عمر
اس وقت قریباً چھ سات سال کی تھی.اس کے بعد علی" ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے یا
صبح کی سفیدی اب آپ کی عمر چالیس سال کے قریب پہنچ گئی تھی اور وقت آ گیا تھا کہ صبح کی سفیدی
افق مشرق میں نمودار ہو.یوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مکہ کی عام
سوسائٹی میں زیادہ خلاملا نہیں کیا مگر ان ایام میں خصوصاً آپ کی طبیعت کا یہ حال تھا کہ دن رات اللہ تعالیٰ
کی طلب اور اُس کی یاد میں مشغول رہتے تھے.مکہ کے پاس شہر سے تین میل کے فاصلہ پر منٹی کی طرف
جاتے ہوئے بائیں جانب کوہ حرا میں ایک غار ہے جس کو غار حراء کہتے ہیں.ان ایام میں آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا عام دستور تھا کہ وہاں جاتے اور غور وفکر اور یاد خدا میں مشغول رہتے.عام طور پر کئی کئی دن کا
کھانا ساتھ لے جاتے اور شہر میں نہ آتے.بعض اوقات حضرت خدیجہ بھی ساتھ جاتی تھیں.یہی وہ زمانہ
ہے جسے قرآن شریف میں تلاش حق کا زمانہ کہا گیا ہے؛ چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدَى
و یعنی اللہ نے تجھے اپنی تلاش میں سرگردان و حیران پایا.پس اُس نے تجھ کو اپنی طرف
آنے کا راستہ بتا دیا.“
اس زمانہ میں رویا صالحہ کا آغاز ہوا جس کا عرصہ چھ ماہ کا بیان ہوا ہے کے گویا نبوت کی ابتدائی سیڑھی
ل : ابن ہشام واسد الغابہ
: بیہقی بحوالہ زرقانی باب مبعث النبی
: سورۃ صحی : ۸
Page 142
۱۲۷
تھی.چنانچہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ :
اَوَّلُ مَا بُدِى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ
الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ.وَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ
وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَالتَّعَبُّدُ اللَّيَالِي
ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَالِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى
خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَ هُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ
یعنی شروع شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رنگ میں وحی کی ابتداء ہوئی
وہ رویا صالحہ کی صورت میں تھی جو آپ نیند کی حالت میں دیکھتے تھے.ہر ایک رؤیا جو آپ
دیکھتے تھے وہ صبح کی سفیدی کی طرح پوری ہوتی تھی.اس زمانہ میں آپ کو خلوت
و تنہائی میں
رہنا بہت محبوب تھا.آپ غارِ حرا میں جاتے اور وہاں کئی کئی رات عبادت کرتے رہتے پھر گھر
آتے اور اپنے ساتھ کچھ اور زاد لے جاتے.جب وہ ختم ہو جاتا تو پھر خدیجہ سے آ کر لے
جاتے.آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ کے پاس خدا کی طرف سے حق آ گیا.اس وقت
آپ غار حرا میں تھے.: بخاری باب بدء الوحی
Page 143
۱۲۸
ابتدائی زندگی پر ایک سرسری نظر
واقعات کی قلت اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ک زندگی کا پہلا دور تم ہو لیکن طبیعت سیر نہیں ور
ہاتھ سے قلم رکھنے کو جی نہیں چاہتا اور دل یہ محسوس کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ابتدائی چالیس سالہ زندگی کے واقعات اس تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں جیسا کہ بعد کے
زمانہ کے محفوظ ہیں.ایک حد تک یہ ایک طبعی امر ہے کیونکہ جس نظر سے آپ کو نبوت کے زمانہ میں دیکھا
جاتا تھا، وہ پہلے زمانہ میں موجود نہیں تھی لیکن پھر بھی اگر ابتدائی مؤرخین کی طرف سے آپ کی قبل از بعثت
زندگی کے حالات پر زیادہ توجہ کے ساتھ نظر ڈالی جاتی اور زیادہ محنت اور زیادہ کوشش کے ساتھ واقعات کی
تلاش کی جاتی تو بعض مزید حالات دریافت ہو سکتے تھے؛ تاہم جو کچھ بھی موجود ہے وہ دوسرے سابقہ
نبیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے اور وہ اس عظیم الشان پاک و بے لوث زندگی کا کافی وشافی ثبوت ہے جو
آپ نے بعثت سے پہلے گزاری.آپ کی امتیت ناظرین نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اس چالیس سالہ زندگی میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی ذکر نہیں آیا.دراصل عرب میں تعلیم بہت ہی کم تھی اور اس
لحاظ سے شرفاء اور عوام میں بہت کم امتیاز تھا بلکہ بڑے بڑے سردار بھی عموماً اسی طرح ان پڑھ اور ناخواندہ
ہوتے تھے جس طرح عوام تھے.مگر اس میں شبہ نہیں کہ ملک میں پڑھے لکھے لوگ بھی کہیں کہیں پائے جاتے
تھے اور ایسے لوگ مکہ میں دوسرے مقامات کی نسبت قدرے زیادہ تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلق یہ ثابت ہے کہ آپ بالکل ناخواندہ اور امی تھے.اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی اُمتیت میں
خدائی تصرف کا بھی ہاتھ تھا تا کہ دنیا میں آپ کے علمی معجزہ کی شان دوبالا ہوکر چپکے.لیکن اس کے ساتھ ہی
یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ نبوت میں چونکہ اکثر مراسلات اور معاہدات وغیرہ آپ کے سامنے تیار
ہوتے اور آپ کی نظر سے گذرتے رہتے تھے.اس لیے آپ کو اپنی عمر کے آخری حصہ میں کچھ حروف
ل قرآن شریف سورۃ اعراف:۱۵۹ وسورۃ عنکبوت : ۴۹
Page 144
۱۲۹
شناسی ہو گئی تھی ، چنانچہ ایک حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھے جانے کے وقت
آپ نے کفار کی طرف سے اعتراض ہونے پر اپنے نام کے ساتھ سے رسول اللہ “ کے الفاظ خود اپنے
ہاتھ سے کاٹ کر ان کی جگہ ابن عبد اللہ کے الفاظ لکھ دیئے تھے.یہ بالکل ممکن ہے کہ اس موقع پر جو مجرد کتب کا لفظ حدیث میں لکھ دینے کے لیے استعمال ہوا ہے
اُس سے مراد لکھا دینے کے ہوں.کیونکہ بعض اوقات عام محاورہ میں لکھنے اور لکھوانے ہر دو کے لیے ایک
ہی لفظ بول دیتے ہیں.اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کا جو حصہ
کاٹا وہ خود اپنے ہاتھ سے کاٹا مگر کاٹنے کے بعد جو کچھ لکھا گیا وہ آپ نے اپنے کاتب سے لکھوایا، لیکن
بہر حال جو بھی مراد لی جاوے اس سے یقیناً آپ کی اُمیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا.بعثت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ تعلقات کا دائرہ بہت ہی محدود نظر
حلقہ احباب
آتا ہے.دراصل شروع سے ہی آپ کی طبیعت علیحدگی پسند تھی اور آپ نے اپنی عمر
کے کسی حصہ میں بھی مکہ کی عام سوسائٹی میں زیادہ خلا ملا نہیں کیا ، تاہم بعض ایسے لوگ بھی تھے جن کے
ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات تھے.ان سب میں ممتاز حضرت ابو بکر یعنی عبداللہ بن ابی قحافہ تھے.جو
قریش کے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قوم میں بڑی عزت
کی نظر سے دیکھے جاتے تھے.دوسرے درجہ پر حکیم بن حزام تھے جو حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے.یہ نہایت
شریف الطبع آدمی تھے.شروع شروع میں یہ اسلام نہیں لائے لیکن اس حالت میں بھی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے.آخر سعادت طبعی اسلام کی طرف
کھینچ لائی.پھر زید بن عمر و
سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات تھے.یہ صاحب حضرت عمرؓ کے قریبی رشتہ دار تھے اور ان
لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی شرک ترک کر رکھا تھا اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی
کی طرف منسوب کرتے تھے مگر یہ اسلام کے زمانہ سے پہلے ہی فوت ہو گئے.بعثت سے پہلے آپ کا مذہب اسلام اپنے تفصیلی مسائل کے ساتھ تو بہر حال بعد میں ہی اترا
ہے
اس لیے بعثت سے پہلے اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کار بند
ہونے کا تو کوئی شخص مدعی نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کوئی ہوا ہے لیکن یہ بات تاریخ سے پایہ ثبوت تک پہنچی ہوئی
ہے کہ بمقتضائے فطرتِ صحیحہ آپ ہمیشہ عرب سوسائٹی کی گندی رسوم سے مجتنب رہے اور شرک بھی آپ
: بخاری کتاب الصلح
Page 145
۱۳۰
نے کبھی نہیں کیا؛ چنانچہ زمانہ نبوت میں آپ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ میں نے بتوں کے
چڑھاوے کا کھانا کبھی نہیں کھایا.اور ایک روایت میں حضرت
علی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ نے کبھی بتوں کو پوجا ہے.آپ نے فرمایا
نہیں.پھر لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے کبھی شراب پی ہے.آپ نے فرمایا نہیں.پھر فرمایا کہ میں ہمیشہ
سے ان باتوں کو قابل نفرت سمجھتا رہا ہوں، لیکن اسلام سے پہلے مجھے شریعت اور ایمان
کا کوئی علم نہیں تھا.ہے
آپ کے اخلاق و عادات یہ بتایا جا چکا ہے کہ بعثت سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش
کے اندرامین کے لقب سے مشہور تھے جو آپ کی امانت و دیانت اور
اخلاق فاضلہ کا بین ثبوت ہے.آپ کی راست گفتاری کا یہ حال تھا کہ ابو جہل جیسا معاند جو آپ کے خون
کا پیاسا تھا ایک دفعہ زمانہ نبوت میں آپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگا :
إِنَّا لَا نُكَلِّ بُكَ وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ -
اے محمد ! ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس بات کو جھوٹا کہتے ہیں جو تو لایا ہے.“
ابوسفیان ہرقل شہنشاہ روم کے سامنے پیش ہوا.تو ہر قل نے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بارے میں پوچھا:
هَلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ؟
” کیا تم نے اس دعوی سے پہلے کبھی اس شخص کا کوئی جھوٹ دیکھا ؟“
ابوسفیان اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پر کار تھا لیکن اس سوال کے جواب میں اُسے
بھی بجز ، یعنی ”نہیں“ کے کوئی جواب نہیں بن پڑا امیہ بن خلف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی
دشمن تھا.لیکن جب حضرت سعد بن معاذ نے اس کو یہ خبر سُنائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری موت
کی پیشگوئی کی ہے تو اُس کے اوسان خطا ہو گئے اور اس نے گھر جا کر اپنی بیوی سے یہ ذکر کیا اور کہا:
وَاللهُ مَا يَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَثَ
"خُدا کی قسم.محمد جب کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ نہیں بولتا.“
پھر النظر بن الحارث اشد ترین معاندین اسلام میں سے تھا لیکن جب اس نے کسی شخص سے یہ کہتے
: سيرة حلبيه جلد اباب ما حفظه الله : سيرة حلبيه باب ماحفظه الله
: بخاری باب بدء الوحی
۵ : بخاری کتاب المغازی
: ترندی
Page 146
۱۳۱
سُنا کہ نعوذ باللہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) جھوٹا ہے تو بے اختیار ہو کر بولا :
قَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيْكُمْ غُلَا مَا حَدَثًا اَرْضَاكُمْ فِيْكُمْ وَاَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا
وَأَعْظَمُكُمُ اَمَانَةٌ حَتَّى إِذَا رَتَيْتُمُ فِى صُدْغَيْهِ الشَّيْبَ وَ جَاءَ كُمْ بِمَا جَاءَ كُمْ بِهِ
قُلْتُم سَاحِرٌ لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ
د یعنی محمد تم میں ہی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا اور وہ تم سب میں سے زیادہ پسندیدہ اخلاق
والا تھا اور سب سے زیادہ راست گو تھا اور سب سے زیادہ امین تھا اور اس کے متعلق تمہاری یہی
رائے رہی.حتی کہ جب تم نے اس کی زلفوں میں سفیدی دیکھی اور وہ بڑھاپے کو پہنچا اور وہ
تمہارے پاس وہ کچھ لایا جو کہ وہ لایا تو تم یہ کہنے لگے کہ وہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے.خدا کی قسم وہ
جھوٹا اور ساحر تو ہر گز نہیں.“
اس سے انظر بن الحارث کی بھی وہی مرا تھی جو ابو جہل نے کہا کہ ہم محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کو جھوٹا
نہیں کہتے بلکہ اس کے لائے ہوئے دین کو جھوٹا کہتے ہیں.پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام شروع کی اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو جمع
کیا اور اُن سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی پچھلی وادی میں ایک بڑ الشکر جمع ہے جو تم پر حملہ
کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو با وجود اس کے کہ بظاہر یہ بات بالکل بعید از امکان تھی.سب نے کہا:
نَعَمُ مَا جَرَّ بُنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا
”ہاں! ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے تجھ کو ہمیشہ صادق پایا ہے.“
آپ نے فرمایا:
تو پھر میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کا عذاب تمہارے قریب آ رہا ہے جس سے اپنے بچاؤ کا
سامان کرلو.“
یہ سب شہادتیں اشد ترین دشمنوں کی ہیں اور مومنوں کی طرف سے تو کسی شہادت کی ضرورت نہیں
کیونکہ اُن کا ایمان لانا ہی ایک زبر دست مجسم شہادت ہے.لیکن میں اس موقع پر آپ کی زوجہ خدیجہ
رضی اللہ عنہا کی شہادت درج کئے بغیر نہیں رہ سکتا.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ
ا : شفا قاضی عیاض و ابن ہشام
: بخاری و مسلم
Page 147
۱۳۲
خدائی فرشتہ وحی لے کر آیا اور آپ نے سخت گھبرا کر خدیجہ سے کہا کہ مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا
ہو گیا ہے.تو خدیجہ نے جو محرم حال تھی بے ساختہ طور پر یہ الفاظ کہے کہ :
كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدِقُ الْحَدِيثَ
وَتَحْمِلُ الكَلَّ و تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ
الْحَقِّ
ہر گز نہیں ہرگز نہیں ! خدا کی قسم ! اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا.آپ رشتہ داروں
کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور صادق القول ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں اور آپ نے
گمشدہ اخلاق کو اپنے اندر جمع کیا ہے اور آپ مہمان نواز ہیں اور حق کی راہ میں لوگوں کے
مددگار ہوتے ہیں.“
یہ اس معزز خاتون کی شہادت ہے جو دن رات اُٹھتے بیٹھتے ، کھاتے پیتے ، سوتے جاگتے آپ کو
دیکھتی تھی.اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمُ
ل : بخاری باب بدء الوحی
Page 148
۱۳۳
آغاز رسالت
طلوع آفتاب صبح کی سفیدی افق مشرق میں نمودار ہو رہی تھی اور آفتاب عالم تاب طلوع کرنے کو
تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اپنے
رنگ میں عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے.رویا صالحہ کا آغاز ہو چکا تھا.اسی حالت میں آنحضرت
صلی
اللہ علیہ وسلم نے چھ ماہ گزارے.اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کی تھی اور طبیعت نبوت ورسالت کی پختگی کو پہنچ چکی
تھی.رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور اس کے آخری عشرہ کے ایام تھے اور پیر کا دن تھا.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم حسب معمول غارِ حرا میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ یکلخت آپ کے سامنے ایک غیر مانوس
ہستی نمودار ہوئی.اُس ربانی رسول نے جو خدائی فرشتہ جبرائیل تھا آپ سے مخاطب ہو کر کہا." اقرأ
پڑھ ، یعنی منہ سے بول یا لوگوں تک پہنچا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.” مَا أَنَا بِقَارِيُّ “.میں تو نہیں پڑھ سکتا.یعنی میں تو یہ کام نہیں کر سکتا.فرشتہ نے یہ جواب سنا تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ مگر آنحضرت کی طرف سے پھر وہی
جواب تھا.فرشتہ نے پھر پکڑا اور زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا مگر ادھر سے پھر وہی تأمل تھا.اس پر اُس ربانی رسول نے آپ کو تیسری دفعہ پکڑا اور نہایت زور سے بھینچا گویا اپنی انتہائی کوشش سے
اس معانقہ کے ساتھ آپ کے قلب پر اثر ڈالتا تھا اور پھر اس تسلی کے بعد کہ اب آپ کی طبیعت اس
ل : بیہقی بحوالہ زرقانی باب مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم
: قَرَءَ کے معنے پیغام پہنچانے کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں اِقْرَأْ مِنِّى السَّلَامَ یعنی میرا سلام
اسے پہنچا دو.دیکھوا قرب الموارد.ے : یہ ایسا ہی جواب تھا جیسا کہ حضرت موسیٰ نے دیا تھا کہ میں نبوت کا اہل نہیں ہوں یہ کام کسی اور کے
سپر دفر مایا جاوے.مگر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس بات کو کون جانتا ہے کہ رسالت کا اہل کون ہے.
Page 149
۱۳۴
پیغام کے لینے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے اس نے آپ کو چھوڑ کر کہا :
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبَّكَ الَّذِي خَلَقَ : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ & اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ نْ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ نْ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ
پڑھ یعنی منہ سے بول یا لوگوں تک پہنچا اپنے رب کا نام ہے جس نے پیدا کیا.پیدا کیا
اس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے.ہاں پڑھ.تیرا رب بہت عزت وشان والا ہے.جس نے قلم کے ذریعہ سے علم سکھایا.سکھایا اس نے انسان کو وہ کچھ جو وہ جانتا نہ تھا.“.یہ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سخت گھبراہٹ اور اضطراب کی تھی
اور دل دھڑک رہا تھا کہ خدا جانے یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہونے والا ہے.اسی حالت میں آپ جلدی
جلدی غار حرا سے نکل کر گھر کی طرف لوٹے اور خدیجہ سے فرمایا.زَمِّلُو نِي - زَمِلُونِی.مجھ پر کوئی
کپڑا ڈالو.مجھ پر کوئی کپڑا ڈالو.حضرت خدیجہ اپنے محبوب خاوند کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئیں اور
جلدی سے آپ کو کپڑا اوڑھا دیا.جب ذرا اطمینان ہوا اور گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے سارا ماجرا
حضرت خدیجہ کوسنایا اور آخر میں فرمایا.لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِی.مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر
پیدا ہو گیا ہے.مگر حضرت خدیجہ جو آپ کی حالت سے خوب واقف تھیں بولیں:
كَلَّا أَبْشِرُ فَوَ اللَّهِ لَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدِقُ
الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ و تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى
نَوَائِبِ الْحَقِّ
نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا بلکہ آپ خوش ہوں.خدا کی قسم اللہ آپ
کو کبھی رسوا نہیں
کرے گا.آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور صادق القول ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں اور
معدوم اخلاق کو آپ نے اپنے اندر جمع کیا ہے اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی
باتوں میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں.“
66
ل : العلق : ۲ تا ۶ ہے : اس جگہ نحوی ترکیب میں لفظ اسم اقرأ کا مفعول ہے.عربی قواعد نحو
کی رُو سے اقرا کے مفعول پر بعض اوقات ب زائد آ جایا کرتی ہے.دیکھو اقرب الموارد.: یعنی اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ انسان
کو قلم کے ذریعہ سے نئے نئے علوم سکھائے جائیں.: بخاری کتاب بدء الوحی.
Page 150
۱۳۵
اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو شرک کا
تارک ہو کر عیسائی مذہب کا پیر و ہو چکا تھا اور گذشتہ صحف انبیاء سے کسی قدر واقف تھا اور اب بوڑھا تھا حتی
کہ اس کی آنکھوں کی بینائی تک بھی جا چکی تھی.اس کے پاس آپ کو لے جا کر حضرت خدیجہ نے کہا.”بھائی ذرا اپنے اس بھتیجے کی بات تو سن لو.“ اُس نے کہا.”ہاں کیا معاملہ ہے؟ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے سب ماجرائنا دیا.جب ورقہ ساری کیفیت سن چکا تو بولا.یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسی
پر وحی لاتا تھا.اے کاش ! مجھ میں طاقت ہوتی.اے کاش ! میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم
تجھے وطن سے نکال دے گی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا.اَوَ مُخْرِجِيَّ هُمُ " کیا
میری قوم مجھے نکال دے گی ؟ ورقہ نے کہا.”ہاں کوئی رسول نہیں آیا کہ اس کے ساتھ اس کی قوم نے
عداوت نہ کی ہو اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کروں گا.“
مگر ورقہ کو یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوئے کیونکہ تھوڑے عرصہ کے بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا.فترة وحى اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا یے اور ایک عرصہ تک جس کا اندازہ ابن عباس کی ایک
روایت کے مطابق چالیس یوم بیان ہوا ہے.یہ سلسلہ رکا رہا.اس زمانہ کو فترة کا زمانہ
کہتے ہیں.گویا آفتاب رسالت کی روشنی ایک دفعہ نظر آئی اور پھر غائب ہوگئی.آپ کے لب ہائے تشنہ پر
بارش کا ایک چھینا پڑا اور پھر بادل پھٹ گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایام سخت گھبراہٹ اور
بے چینی کی حالت میں گزارے.دن رات اُٹھتے بیٹھتے یہی خیال تھا کہ خدا جانے یہ کیا معاملہ ہے اور کیا
ہونے والا ہے اور اس غیر مانوس غیبی رسول کا آنا کیا معنے رکھتا ہے اور کیا یہ پیام وسلام خدا کی طرف سے
ہے یا میرے اپنے نفس کا ہی کوئی مخفی پر تو ہے ؟ ان سوالات نے آپ کو سخت بے چین کر رکھا تھا حتی کہ
حدیث میں آتا ہے کہ ان ایام میں آپ کو اتنی گھبراہٹ تھی کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر
چڑھ گئے اور ارادہ کیا کہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں مگر ہر ایسے موقع پر
الہی فرشتہ آواز دیتا.دیکھو محمد ایسا نہ کرو تم واقعی اللہ کے رسول ہو.“ یہ آواز سُن کر آپ رُک جاتے
مگر پھر بے چینی اور اضطراب کی حالت پیدا ہوتی تو بے اختیار ہو کر پھر اپنے آپ کو ہلاک کر دینے
کے لیے تیار ہو جاتے ہے
دو
ل : بخاری باب بدء الوحی.۲: بخاری باب مذکور
ه : بخاری باب بدء الوحی
زرقانی جلدا باب مراتب الوحی
Page 151
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مندرجہ بالا حدیث کے الفاظ میں ظاہری معنے مراد نہ ہوں اور اپنے آپ کو بلندی
سے گرا کر زندگی کا خاتمہ کر دینے کا یہ مطلب ہو کہ چونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس غیبی فرشتہ کا نظر آنا
نفس ہی کا پر تو نہ ہو یا یہ سب نظارہ خدا کی طرف سے بطور امتحان کے ہو، اس لیے آپ نے یہ ارادہ کیا کہ
اپنے نفس کو مزید گرا کر اور پست و مغلوب کر کے گویا خدا کی راہ میں اسے بالکل ہی مار دیں.اس صورت
میں پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا دینے کے الفاظ گویا بطور استعارہ کے سمجھے جائیں گے.بہر حال خواہ کوئی
بھی معنے ہوں آپ کے لیے یہ دن بڑی کش مکش کے دن تھے اور اسی کش مکش کی حالت میں آپ ایک دن
غارِ حرا سے گھر کی طرف واپس آرہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی.گویا کوئی شخص آپ کو مخاطب کر رہا
ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے، دائیں بائیں سب طرف دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا.آخر
آپ نے اُوپر نظر اُٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک عظیم الشان گرسی پر وہی
فرشتہ بیٹھا ہے جو غارِ حرا میں آپ کو نظر آیا تھا.آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو سہم گئے اور گھبرائے ہوئے
جلدی جلدی گھر آئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا: دَبَّرُونِي ! دَقِّرُونِی ! مجھ پر کوئی کپڑا ڈھانک
دو.خدیجہ نے جلدی سے کپڑا اوڑھا دیا اور آپ لیٹ گئے.آپ کا لیٹنا تھا کہ ایک پر جلال آواز آپ
کے کانوں میں آئی:
فَاهْجُرْ
يَايُّهَا الْمُدَّخِرُ قُمْ فَانْذِرْةُ وَرَبَّكَ فَكَبَرْنَ وَثِيَابَكَ فَطَرْتُ وَالرُّجْزَ
د یعنی اے چادر میں لیٹے ہوئے شخص! اُٹھ کھڑا ہو.اور لوگوں کو خدا کے نام پر بیدار کر.اُٹھ اور اپنے رب کی بڑائی کے گیت گا اور اپنے نفس کو پاک وصاف کر اور ہر قسم کے شرک سے
66
پر ہیز کر “
اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری ہو گیا.آغا ز تبلیغ اب آپ کی طبیعت میں یکسوئی اور اطمینان تھا؛ چنانچہ آپ نے لوگوں کو تو حید باری تعالیٰ کی
طرف بلانا شروع کیا اور شرک کے خلاف تعلیم دینے لگے مگر شروع شروع میں آپ نے
اپنے مشن کا کھلم کھلا اظہار نہیں فرمایا بلکہ نہایت خاموشی کے ساتھ کارروائی شروع کی اور صرف اپنے ملنے
والوں کے حلقہ تک اپنی تعلیم کو محد و در کھاتے
ل : سورة مدثر : ۲ تا ۵ و بخاری ابواب التفسیر و باب بدء الوحی.: زرقانی وطبری
Page 152
۱۳۷
گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کا ڈھانچہ بیان کرنے کے لیے اصل
اسلام کا پیغام
موقع آگے آئے گا لیکن ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ بھی ایک مختصر سا خا کہ اسلام
کا درج کر دیا جائے تا کہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا اور اس
کے اصول کیا تھے.سو جاننا چاہئے کہ جو مذہب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اس کا
نام اسلام ہے جس کے معنے اپنے آپ کو خدا کے سپر د کر دینے کے ہیں اور یہی آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا
حقیقی خلاصہ ہے.آپ کے مذہب کا پہلا اور سب سے بڑا اصول تو حید باری تعالیٰ ہے.یعنی یہ کہ اس دنیا
کا خالق و مالک ایک خدا ہے جو اپنی ذات وصفات میں واحد لاشریک ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ
رہے گا اور زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی پیدا کردہ اور اسی کے سہارے سے قائم ہے، اس لیے اس کے سوا
کسی کی پرستش جائز نہیں اور وہ تمام معبود جو خدا کے سوالوگوں نے بنارکھے ہیں وہ سب فرضی اور باطل
ہیں.یہ وہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا اصول ہے جو آپ نے اہلِ مکہ کے سامنے پیش کیا.دوسرا
اصول آپ نے یہ بیان
کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک خاص غرض وغایت کے ماتحت پیدا کیا ہے اور وہ یہ
کہ لوگ اُسے پہچان کر اس کے رنگ میں رنگین ہوں اور اپنے لیے ابدی ترقی کا سامان پیدا کر یں اور اس
غرض کے لیے اُس نے انسانی زندگی کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا ہے.ایک دنیا کی زندگی جو کہ دارالعمل ہے
اور ایک آخرت کی زندگی جو کہ دارالجزاء ہے اور ان ہر دو زندگیوں کے درمیان موت کو حد فاصل مقر ر کیا
گیا ہے.تیسرا اصول آپ نے یہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے رسول اور نبی
مبعوث کرتا رہتا ہے جو خدا سے علم پا کر دنیا کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں.ایسے رسول اور نبی ہر قوم اور
ہر ملک اور ہر زمانہ میں گذرے ہیں اور انہیں میں سے آپ بھی خدا کے ایک رسول ہیں.یہ وہ تین
اصل الاصول ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مشن کی بنیاد تھے.مگر جوں جوں زمانہ گذرتا گیا
بعض مزید اصول اور ان اصول کی مزید فروع اور مزید تفصیلات نازل ہوتی گئیں حتی کہ آپ کی لائی ہوئی
تعلیم موجودہ قرآن کریم کی صورت میں اپنی تکمیل کو پہنچ گئی اور آپ سب اولین و آخرین کے سردار
اور خاتم النبیین اور آخری اور کامل شریعت لانے والے قرار دئیے گئے.سب سے پہلا مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کی تبلیغ شروع کی تو سب
سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھیں جنہوں نے ایک لمحہ کے
لیے بھی تردد نہیں کیا.حضرت خدیجہ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کے متعلق
Page 153
۱۳۸
مؤرخین میں اختلاف ہے.بعض حضرت
ابو بکر عبداللہ بن ابی قحافہ کا نام لیتے ہیں.بعض حضرت علی کا جن
کی عمر اس وقت صرف دس سال کی تھی اور بعض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت
زید بن حارثہ کا.مگر ہمارے نزدیک یہ جھگڑا فضول ہے.حضرت علی اور زید بن حارثہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے اور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا فرمانا تھا اور ان کا ایمان لانا بلکہ ان کی طرف سے تو شاید کسی قولی اقرار کی بھی ضرورت نہ تھی.پس ان کا نام بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں اور جو باقی رہے ان سب میں سے حضرت ابوبکر مسلمہ طور پر
مقدم اور سابق بالایمان تھے؛ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعرحستان بن ثابت انصاری
حضرت ابو بکر کے متعلق کہتے ہیں.إِذَا تَذَكَّرُتَ شَجُوا مِنْ أَخِي ثِقَةٍ فَاذْكُرُ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا
خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهَا بَعْـدَا النَّبِيِّ وَ أَوْفَاهَا بِمَا حَمَلَا
الثَّانِي التَّالِيُّ الْمَحْمُودَ مَشْهَدَهُ وَأَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَا
یعنی ” جب تمہارے دل میں کبھی کوئی درد آمیز یاد تمہارے کسی اچھے بھائی کے متعلق پیدا
ہوتو اس وقت اپنے بھائی ابو بکر کو بھی یاد کر لیا کرو.اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے جو یادرکھنے
کے قابل ہیں.وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے زیادہ متقی اور سب
سے زیادہ منصف مزاج تھا اور وہ سب سے زیادہ پورا کرنے والا تھا اپنی اُن ذمہ داریوں کو جو
اس نے اٹھا ئیں.ہاں ابو بکر وہی تو ہے جو غار ثور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
دوسرا شخص تھا جس نے اپنے آپ کو آپ کی اتباع میں بالکل محو کر رکھا تھا اور وہ جس کام میں
بھی ہاتھ ڈالتا تھا اسے خوبصورت بنا دیتا تھا اور وہ ان سب لوگوں میں سے پہلا تھا جو رسول پر
ایمان لائے ہے
حضرت ابو بکر اپنی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قریش میں بہت مکرم و معزز تھے اور اسلام میں
تو ان کو وہ رتبہ حاصل ہوا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں.حضرت ابو بکر نے ایک لمحہ کے لیے بھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوئی میں شک نہیں کیا بلکہ سنتے ہی قبول کیا اور پھر انہوں نے اپنی ساری
توجہ اور اپنی جان اور مال کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت میں وقف کر دیا.: طبری
Page 154
۱۳۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں ابوبکر کو زیادہ عزیز رکھتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد وہ
آپ کے پہلے خلیفہ ہوئے.اپنی خلافت کے زمانہ میں بھی انہوں نے بے نظیر قابلیت کا ثبوت دیا.حضرت ابو بکر کے متعلق یورپ کا مشہور مستشرق سپر نگر لکھتا ہے کہ:
ابو بکر کا آغاز اسلام میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر ایمان لانا اس بات کی سب سے
بڑی دلیل ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) خواہ دھوکا کھانے والے ہوں مگر دھوکا دینے والے ہرگز
نہیں تھے.بلکہ صدقِ دل سے اپنے آپ کو خدا کا رسول یقین کرتے تھے.“
اور سرولیم میور کو بھی سپر نمر کی اس رائے سے کلی اتفاق ہے.سابقین حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت علی اور زید بن حارثہ کے بعد اسلام لانے والوں میں
پانچ اشخاص تھے جو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے اور یہ سب کے سب اسلام میں
ایسے جلیل القدر اور عالی مرتبہ اصحاب نکلے کہ چوٹی کے صحابہ میں شمار کئے جاتے ہیں.ان کے نام یہ ہیں :
اول حضرت عثمان بن عفان جو خاندان بنوامیہ میں سے تھے.اسلام لانے کے وقت اُن کی عمر قریباً
تمہیں سال کی تھی.حضرت عمرؓ کے بعد وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہوئے.حضرت عثمان
نهایت با حیا، با وفا، نرم دل، فیاض اور دولتمند آدمی تھے.چنانچہ کئی موقعوں پر انہوں نے اسلام کی بہت
بہت مالی خدمات کیں.حضرت عثمان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے
کہ آپ نے انہیں پے در پے اپنی دولڑ کیاں شادی میں دیں جس کی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہتے ہیں.دوسرے عبدالرحمن بن عوف تھے جو خاندان بنو زہرہ سے تھے جس خاندان سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں.نہایت سمجھدار اور بہت سمجھی ہوئی طبیعت کے آدمی تھے.حضرت عثمان کی
خلافت کا سوال انہی کے ہاتھ سے طے ہوا تھا.اسلام لانے کے وقت ان کی عمر قریباً تمہیں سال کی تھی.عہد عثمانی میں فوت ہوئے.تیسرے سعد بن ابی وقاص تھے جو اس وقت بالکل نوجوان تھے یعنی اس وقت اُن کی عمر انیس سال
کی تھی.یہ بھی بنوزہرہ میں سے تھے اور نہایت دلیر اور بہادر تھے.حضرت عمرؓ کے زمانہ میں عراق انہی کے
ہاتھ پر فتح ہوا.امیر معاویہ کے زمانہ میں فوت ہوئے.چوتھے زبیر بن العوام تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے.یعنی صفیہ بنت
لائف آف محمد مصنفہ میور صفحه ۵۶
Page 155
۱۴۰
عبدالمطلب کے صاحبزادے تھے اور بعد میں حضرت ابو بکر کے داماد ہوئے.یہ بنو اسد میں سے تھے اور
اسلام لانے کے وقت ان کی عمر صرف پندرہ سال
کی تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کوغزوہ خندق
کے موقع پر ایک خاص خدمت سرانجام دینے کی وجہ سے حواری کا خطاب عطا فرمایا تھا.زبیر حضرت علیؓ کے
عہد حکومت میں جنگ جمل کے بعد شہید ہوئے.پانچویں طلحہ بن عبید اللہ تھے جو حضرت ابو بکر کے خاندان یعنی قبیلہ بنو تیم میں سے تھے اور اس
وقت بالکل نوجوان تھے.طلحہ بھی اسلام کے خاص فدایان میں سے تھے.حضرت علی کے عہد میں جنگ جمل
میں شہید ہوئے.یہ پانچوں اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی اُن دس اصحاب میں داخل ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خاص طور پر جنت کی بشارت دی تھی اور جو آپ کے نہایت مقرب
صحابی اور مشیر شمار ہوتے تھے.ان لوگوں کے بعد اور لوگ جو شروع شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ بعض تو
قریش میں سے تھے اور بعض دوسرے قبائل میں سے تھے.ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں :
ابوعبیدہ بن عبداللہ بن الجراح جن کے ہاتھ پر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں شام فتح ہوا.یہ نہایت نیک
اور صوفی مزاج آدمی تھے جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امین الملۃ کا خطاب عطا ہوا تھا.ابو عبیدہ قریش کے قبیلہ بنو خلج میں سے تھے جنہیں بعض اوقات فہر بن مالک کی طرف منسوب کر کے فہری بھی
کہہ لیتے تھے.حضرت عائشہ کی نظر میں ابو عبیدہ کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ اگر حضرت
عمرہ کی وفات پر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو وہی خلیفہ ہوتے.حضرت ابو بکر بھی ابو عبیدہ کی بہت قدر کرتے
تھے ، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جن لوگوں کو حضرت ابو بکر نے خلافت کا اہل قرار دیا تھا،
اُن میں سے ابو عبیدہ بھی تھے.ابو عبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں.حضرت عمرؓ کے زمانہ میں دبائے طاعون
سے شہید ہوئے.پھر عبیدۃ بن الحارث تھے جو بنو مطلب میں سے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار
تھے.پھر ابوسلمہ بن عبد الاسد تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے اور بنو مخزوم سے تعلق
رکھتے تھے.اُن کی وفات پر اُن کی بیوہ ام سلمہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی.ل : اصابه واسدالغابہ وابن ہشام وطبری وزرقانی
Page 156
۱۴۱
ابو حذیفہ بن عتبہ تھے جو بنوامیہ میں سے تھے.ان کا باپ عتبہ بن ربیعہ سردارانِ قریش میں سے تھا.ابوحذیفہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے جو حضرت ابو بکر کے زمانہ خلافت میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی
تھی.سعید بن زید تھے جو بنو عدی میں سے تھے اور حضرت عمر کے بہنوئی تھے.یہ زید بن عمرو بن نفیل کے
صاحبزادے تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی شرک ترک کر رکھا تھا.سعید بھی عشرہ مبشرہ میں سے
ہیں.امیر معاویہ کے زمانہ میں فوت ہوئے.عثمان بن مظعون تھے جو بنو حج میں سے تھے.نہایت صوفی
مزاج آدمی تھے.انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی شراب ترک کر رکھی تھی اور اسلام میں بھی تارک دنیا ہونا
چاہتے تھے مگر آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے کہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے اس کی
اجازت نہیں دی.ارقم بن ابی ارقم جن کے مکان کو جو کوہ صفا کے دامن میں تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بعد میں اپنا تبلیغی مرکز بنایا.ارقم بنومخزوم میں سے تھے.پھر عبداللہ بن جحش اور عبید اللہ بن جحش تھے.یہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے مگر قبیلہ قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے.زینب بنت جحش جو بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں انہی کی بہن تھیں.عبید اللہ بن جحش
ان لوگوں میں سے تھا.جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی بت پرستی ترک کر رکھی تھی.اسلام آیا تو وہ مسلمان
ہو گیا، لیکن جب وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تو کسی وجہ سے وہاں اسلام سے منحرف ہو کر عیسائی ہو
گیا.اس کی بیوہ ام حبیبہ جو قریش کے مشہور رئیس ابوسفیان کی لڑکی تھی بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے عقد میں آئی ہے
ان لوگوں کے علاوہ عبداللہ بن مسعودؓ تھے جو غیر قریشی تھے اور قبیلہ ھذیل سے تعلق رکھتے تھے.عبداللہ
ایک بہت غریب آدمی تھے اور عقبہ بن ابی معیط رئیس قریش کی بکریاں چرایا کرتے تھے.اسلام لانے
کے بعد یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے اور آپ کی صحبت سے بالآ خر نہایت عالم و فاضل
بن گئے.فقہ حنفی کی بنیا د زیادہ تر انہی کے اقوال و اجتہادات پر مبنی ہے.پھر بلال بن رباح تھے جو
امیہ بن خلف کے حبشی غلام تھے.ہجرت کے بعد مدینہ میں اذان دینے کا کام انہی کے سپر د تھا.مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا لیکن جب حضرت عمر کے زمانہ خلافت
میں شام فتح ہوا تو ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے اصرار پر انہوں نے پھر اذان کہی جس پر سب کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا؛ چنانچہ وہ خود اور حضرت عمرؓ اور دوسرے اصحاب جو اس وقت موجود تھے اتنے
ل: اسد الغابه
Page 157
۱۴۲
روئے کہ ہچکی بندھ گئی.حضرت عمرؓ کو بلال سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمرؓ نے
فرمایا.آج مسلمانوں کا سردار گذر گیا.یہ ایک غریب حبشی غلام کے متعلق بادشاہ وقت کا قول تھا.پھر
عامر بن فہیرہ تھے جن کو حضرت ابو بکر نے غلامی سے آزاد کر کے خود اپنے پاس نوکر رکھ لیا تھا.پھر خباب بن
الارت تھے جو ایک آزاد شدہ غلام تھے اور اُن دنوں مکہ میں لوہار کا کام کیا کرتے تھے.پھر ابوذر تھے جو
قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے.انہوں نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سُنا تو تحقیقات کے لیے
اپنے بھائی کو مکہ بھیجا.چنانچہ وہ مکہ آیا اور واپس جا کر ابوذر کو حالات سے اطلاع دی ، مگر اس سے ابوذر
کی تسلی نہیں ہوئی اس لیے اس کے بعد وہ خود مکہ میں آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر
مسلمان ہو گئے.ان کے اسلام لانے کا قصہ بخاری میں مفصل درج ہے اور بہت دلچسپ ہے.ابوذر
نہایت زاہد و صوفی مزاج آدمی تھے.اُن کا عقیدہ تھا کہ کسی صورت میں بھی مال جمع کرنا جائز نہیں ہے.اس بناء پر بعض اوقات بعض دوسرے صحابہ سے ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا.کے
یہ وہ چند لوگ ہیں جو ابتدائی تین چار سال میں اسلام لائے.ان میں سے شادی شدہ لوگوں کے بیوی
بچے بھی عموماً ان کے ساتھ تھے ، چنانچہ اس زمانہ میں مسلمان ہونے والی عورتوں میں مؤرخین نے حضرت
خدیجہ کے بعد اسماء بنت ابی بکر اور فاطمہ بنت خطاب زوجہ سعید بن زید کا نام خاص طور پر لیا ہے.ان کے
علاوہ عورتوں میں عباس بن عبد المطلب کی بیوی اُمّم فضل بھی ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں مگر یہ عجیب
بات ہے کہ اس وقت تک عباس خود اسلام نہیں لائے تھے.بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین چار
سالہ تبلیغی جد وجہد کا نتیجہ یہی چند گنتی کی جانیں تھیں.مگر ان سابقین الاولین میں سے سوائے حضرت ابوبکر
کے ایک بھی ایسا نہ تھا جو قریش میں کوئی خاص اثر یا وجاہت رکھتا ہو.بعض غلام تھے اور اکثر لوگ غریب اور
کمزور تھے.بعض البتہ قریش کے اعلیٰ گھرانوں سے بھی تعلق رکھتے تھے.مگر ان میں سے بھی زیادہ تر
نوجوان تھے.بلکہ بعض کو تو گویا بچے ہی کہنا چاہئے اس لیے وہ ابھی اس حالت کو نہ پہنچے تھے کہ اپنے قبیلے
میں کوئی اثر پیدا کرسکیں اور جو معمر تھے وہ غربت یا کسی اور وجہ سے کوئی اثر نہ رکھتے تھے.اس وجہ سے قریش
میں یہ عام خیال
تھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو صرف چھوٹے اور کمز ور لوگوں نے مانا ہے؛ چنانچہ جب کئی
سال بعد ہر قل شہنشاہ روم نے رئیس مکہ ابوسفیان سے دریافت کیا کہ کیا محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کو بڑے
لوگ مانتے ہیں یا کہ کمزور اور چھوٹے لوگ؟" تو ابوسفیان نے یہی جواب دیا کہ کمزور اور چھوٹے لوگ
ل : بخاری کتاب بدء الخلق باب اسلام ابی ذر
: اصابہ - اسدالغابہ
Page 158
۱۴۳
مانتے ہیں.جس پر ہر قل نے کہا اور خوب کہا کہ اللہ کے رسولوں کو شروع شروع میں چھوٹے لوگ ہی مانا
کرتے ہیں لے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینے کا طریق اس موقع پر یہ ذکر نامناسب نہ ہوگا کہ
جب کوئی شخص مسلمان ہونے کے لئے
آتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مقررہ الفاظ
میں اسلام کا اقرار کرواتے تھے اور یہ عہد لیتے تھے کہ آئندہ وہ ہر معروف امر میں آپ کی فرمانبرداری
کرے گا.اسلام کے اقرار میں اصولی باتوں کا صراحت کے ساتھ ذکر کروا کے اقرار لیا جاتا تھا مثلاً یہ کہ
خدا کو ایک واحد لا شریک یقین کروں
گا اور کسی قسم کا شرک نہیں کروں
گا اور ہر قسم کے اعمال شنیعہ مثلاً چوری،
زنا، قتل، جھوٹ وغیرہ سے پر ہیز کروں گا وغیرہ وغیرہ.عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے آپ اقرار تو یہی
لیتے تھے جو مردوں سے لیا جاتا تھا ، مگر آپ عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے بلکہ صرف زبانی
اقرار لے لیا جاتا تھا.بعد میں جب جہاد بالسیف کے متعلق احکام نازل ہوئے تو آپ نے بیعت میں جہاد
کے متعلق بھی الفاظ زیادہ فرما دیئے، لیکن عورتوں کی بیعت آخر تک اسی ابتدائی صورت میں قائم رہی ہے
بیعت کے علاوہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ آپ غیر محرم عورتوں کے ساتھ مصافحہ
نہیں کرتے تھے.اور پر وہ کا حکم نازل ہونے کے بعد تو شرعاً غیر محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے پر اپنی
زینت کا اظہار خواہ وہ نظر کے ذریعہ ہو یا لمس وغیرہ کے ذریعہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے
ابتدائی اخفا اور قریش کا رویہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں قریباً تین برس تک اسلام
کی تبلیغ کو عموماً خفیہ رکھا.چنانچہ اس زمانہ میں مسلمانوں کا کوئی
خاص مرکز بھی نہ تھا جہاں وہ جمع ہو سکتے.بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی تبلیغ سے جو
متلاشیان حق آتے تھے اُن سے آپ عموماً اپنے مکان کے اندر ہی ملتے تھے یا شہر سے باہر کسی جگہ ملاقات
فرماتے تھے.اس اخفا کا یہاں تک اثر تھا کہ بعض اوقات خود مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اسلام کا پتہ نہ
ل : بخاری باب بدء الوحی
: ابن ہشام ذکر بیعت عقبہ اولیٰ و عقبہ ثانیہ و قرآن شریف سورة ممتحنه رکوع ۲ و بخاری باب وفود الانصار
الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.نیز بخاری کتاب الاحکام باب بیعۃ النساء
: بخاری کتاب الاحکام باب بیعۃ النساء
قرآن کریم سورة نور : ۳۱
Page 159
۱۴۴
لگتا تھا جس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانہ میں مسلمان اپنے اسلام کو عام طور پر چھپاتے تھے اور سردارانِ قریش
کے کانوں تک تو بہت ہی کم خبر پہنچتی تھی لیکن اگر کبھی خبر پہنچ بھی جاتی تو بھی ان کی طرف سے ان ایام میں
عموماً مسلمانوں سے کوئی تعارض نہ ہوتا تھا بلکہ اُن کی مخالفت عملاً ہنسی مذاق تک ہی محدو درہتی تھی کیونکہ وہ
اس تمام کا رروائی کو ایک بچوں کا کھیل سمجھتے تھے یا اگر کبھی کوئی شخص زیادہ بختی سے مخالفت کرتا بھی تھا تو یہ اس کا
ذاتی فعل ہوتا تھا اور اسلام کے خلاف قریش کی طرف سے اس وقت کوئی متحدہ مخالفانہ کوشش نہ تھی.ابتدائی زمانہ کے ارکانِ اسلام اصول اسلام کا ذکر اوپر گذر چکا ہے یعنی یہ کہ اس ابتدائی زمانہ
میں جب کہ شریعت اسلامی کے نزول کی ابتدا تھی ارکان اسلام
میں سے صرف ایمان باللہ اور توحید پر اصل زور تھا.اس کے بعد ایمان بالرسل، بعث بعد الموت اور
جزا سزا کا عقیدہ تھا اور گو در حقیقت یہ وہ بنیادی اصول ہیں کہ اگر غور سے دیکھو تو سب کچھ ان کے اندر
آ جاتا ہے لیکن جس طرح بعد میں یہ اور دوسری اصولی باتیں تدوینی رنگ میں ارکان ایمان قرار دی گئیں
یہ حال اوائل میں نہ تھا.اسی طرح ارکانِ اعمال کا حال تھا بلکہ اعمال میں تو موجودہ ارکان یعنی نماز،
روزہ ، حج ، زکوۃ وغیرہ میں سے کوئی رکن بھی اس وقت تک باقاعدہ طور پر قائم نہ ہوا تھا.البتہ احادیث سے
اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا میں جبرائیل نے آپ کو نماز اور وضو کا طریق سکھا دیا تھا مگر با قاعدہ پانچ
وقت کی نماز بہت بعد میں شروع ہوئی اور روزہ وغیرہ تو اس سے بھی بہت عرصہ بعد میں شروع ہوئے.ابتداء میں صرف نماز تھی اور وہ بھی ایک نفلی رنگ رکھتی تھی یعنی ان ابتدائی ایام میں مسلمان اپنے طور
پر گھروں میں یا مکہ کے پاس کی گھاٹیوں میں دو دو چار چار مل کر جب موقع ملا ایک عام عبادت کے
رنگ میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے؛ چنانچہ اس ابتدائی زمانہ کے متعلق مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مکہ کی کسی گھائی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک اس طرف سے
ابوطالب کا گذر ہوا.ابوطالب کو ابھی تک اسلام کی کوئی خبر نہ تھی اس لیے وہ کھڑا ہو کر نہایت حیرت سے یہ
نظارہ دیکھتارہا.جب آپ نماز ختم کر چکے تو اس نے پوچھا ” بھتیجے یہ کیا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.چا! یہ دین الہی اور دین ابراہیم ہے.“ اور آپ نے ابوطالب
کو مختصر طور پر اسلام کی دعوت دی لیکن ابو طالب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ”میں اپنے باپ دادا کا مذہب
نہیں چھوڑ سکتا.مگر ساتھ ہی اپنے بیٹے حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر بولا.”ہاں بیٹا تم بے شک
محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) کا ساتھ دو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ تم کو سوائے نیکی کے اور کسی طرف نہیں
Page 160
۱۴۵
بلائے گا.غالباً اسی زمانہ کے قریب کا ایک اور واقعہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور چند اور مسلمان مل کر کسی
گھائی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین وہاں آ نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کو ایک نئے رنگ
کی عبادت کرتے دیکھ کر ڈانٹا.جس پر با ہم کچھ تکرار بھی ہوگئی ہے
کھلی تبلیغ کا آغاز یہ ابتدائی زمانہ اسی طرح خاموش اور خفیہ تبلیغ میں گذر رہا تھا اور بعثت نبوی پر قریباً
تین سال گذر چکے تھے اور اب چوتھا سال شروع تھا کہ الہی حکم نازل ہوا کہ
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ “
،،
دو یعنی اے رسول ! جو حکم تجھے دیا گیا ہے وہ کھول کھول کر لوگوں کو سنادے “.اور اس کے قریب ہی یہ آیت اتری کہ: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.یعنی اپنے
قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار و بیدار کر ؟
جب یہ احکام اُترے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکار کر اور
ہر قبیلہ کا نام لے لے کر قریش کو بلایا.جب سب لوگ جمع ہو گئے.تو آپ نے فرمایا: ”اے قریش ! اگر
میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کو
مانو گے؟ بظاہر یہ ایک بالکل نا قابل قبول بات تھی مگر سب نے کہا.”ہاں ہم ضرور مانیں گے کیونکہ
ہم نے تمہیں ہمیشہ صادق القول پایا ہے.آپ نے فرمایا تو پھر سنو! میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے
عذاب کا لشکر تمہارے قریب پہنچ چکا ہے.خدا پر ایمان لاؤ تا اس عذاب سے بچ جاؤ.“ جب قریش نے
یہ الفاظ سنے تو کھل کھلا کر ہنس پڑے اور آپ کے چچا ابولہب نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا.” تبا لَكَ
الِهَذَا جَمَعْتَنَا.“ محمد تو ہلاک ہو.کیا اس غرض سے تو نے ہم کو جمع کیا تھا ؟“ پھر سب لوگ ہنسی مذاق
کرتے ہوئے منتشر ہو گئے.اقرباء کی دعوت انہی دنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے
ارشاد فر مایا کہ ایک
دعوت کا انتظام کرو اور اس میں بنو عبدالمطلب کو بلا ؤ تا کہ اس ذریعہ سے اُن تک
پیغام حق پہنچایا جاوے؛ چنانچہ حضرت علی نے دعوت کا انتظام کیا اور آپ نے اپنے سب قریبی رشتہ داروں
ل ابن ہشام بابِ ابْتِدَاءُ مَا فَرَضَ الله
: طبری
: قرآن شریف سورۃ حجر : ۹۵
ه : بخاری قصه اسلام ابی ذر
قرآن شریف سورۃ شعراء : ۲۱۵
د: طبری و خمیس
Page 161
۱۴۶
کو جو اس وقت کم و بیش چالیس نفوس تھے اس دعوت میں بلایا.جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ تقریر
شروع کرنی چاہی مگر بد بخت ابو لہب نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے سب لوگ منتشر ہو گئے.اس پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ یہ موقع تو جاتا رہا اب پھر دعوت کا انتظام کرو.“
چنانچہ آپ کے رشتہ دار پھر جمع ہوئے اور آپ نے انہیں یوں مخاطب کیا کہ ”اے بنوعبدالمطلب ! دیکھو میں
تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلہ کی طرف نہیں لایا.میں تمہیں خدا کی طرف بلاتا ہوں.اگر تم میری بات مانو تو تم دین ودنیا کی بہترین نعمتوں کے وارث بنو
گے.اب بتاؤ اس کام میں میرا کون مددگار ہو گا ؟ سب خاموش تھے اور ہر طرف مجلس میں ایک سناٹا تھا
کہ یکانت ایک طرف سے ایک تیرہ سال کا دبلا پتلا بچہ جس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اُٹھا اور یوں گویا
ہوا.گو میں سب میں کمزور ہوں اور سب میں چھوٹا ہوں مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا.‘ یہ حضرت علیؓ کی
آواز تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے یہ الفاظ سنے تو اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھ کر
فرمایا.اگر تم جانو تو اس بچے کی بات سنو اور اسے مانو.حاضرین نے یہ نظارہ دیکھا تو بجائے عبرت
حاصل کرنے کے سب کھل کھلا کر ہنس پڑے اور ابولہب اپنے بڑے بھائی ابو طالب سے کہنے لگا ”لواب
محمد تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی پیروی اختیار کرو.اور پھر یہ لوگ اسلام اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی کمزوری پر ہنسی اُڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے.“
دار ارقم میں پہلا تبلیغی مرکز غالباً انہی ایام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ سلم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ مکہ
میں ایک تبلیغی مرکز قائم کیا جاوے.جہاں مسلمان نماز وغیرہ کے لیے
بے روک ٹوک جمع ہوسکیں اور امن واطمینان اور خاموشی کے ساتھ باقاعدہ اسلام کی تبلیغ کی جاسکے.اس
غرض کے لیے ایک ایسے مکان کی ضرورت تھی جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو.چنانچہ آپ نے ایک نو مسلم ارقم
بن ابی ارقم کا مکان پسند فرمایا.جو کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا.اس کے بعد تمام مسلمان یہیں جمع
ہوتے.یہیں نماز پڑھتے.یہیں متلاشیان حق آتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تبلیغ
فرماتے.اسی وجہ سے یہ مکان تاریخ میں خاص شہرت رکھتا ہے اور دار الاسلام کے نام سے مشہور ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً تین سال تک دارِ ارقم میں کام کیا.یعنی بعثت کے چوتھے
سال آپ نے اسے اپنا مرکز بنایا اور چھٹے سال کے آخر تک آپ نے اُس میں اپنا کام کیا.مؤرخین لکھتے
طبری
Page 162
۱۴۷
ہیں کہ دار ارقم میں اسلام لانے والوں میں آخری شخص حضرت عمرؓ تھے جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو
بہت تقویت پہنچی اور وہ دار ارقم سے نکل کر بر ما تبلیغ کرنے لگ گئے.دار ارقم میں جو اشخاص ایمان لائے وہ بھی سابقین میں شمار ہوتے ہیں.اُن میں سے زیادہ مشہور
یہ ہیں.اوّل مصعب بن عمیر جو بنو عبد الدار میں سے تھے اور بہت شکیل اور حسین تھے اور اپنے خاندان
میں نہایت عزیز و محبوب سمجھے جاتے تھے یہ وہی نوجوان بزرگ ہیں جو ہجرت سے قبل یثرب میں پہلے
اسلامی مبلغ بنا کر بھیجے گئے اور جن کے ذریعہ مدینہ میں اسلام پھیلا.پھر زید بن الخطاب تھے جو حضرت عمرؓ
کے بڑے بھائی تھے.یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ میں شہید ہوئے.حضرت عمرؓ کو ان کی وفات کا بہت صدمہ ہوا؛ چنانچہ جب اُن کے عہد خلافت میں کسی شخص نے اُن کے
سامنے اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایسے شعر کہہ سکتا تو میں بھی اپنے بھائی
کا ایسا مرثیہ کہتا.اُس شخص نے جواب دیا.”اے امیر المؤمنین ! جس قسم کی مبارک موت آپ کے
بھائی کو نصیب ہوئی ہے وہ اگر میرے بھائی کو نصیب ہوتی تو میں کبھی بھی اُس کا نوحہ نہ کرتا اور مرثیہ نہ
کہتا.“ حضرت عمرؓ کی طبیعت بڑی نکتہ شناس تھی.فرمایا.خُدا کی قسم جس طرح آج تم نے اس قول سے
مجھے تسلی دی ہے ایسی کبھی کسی نے نہیں دی اور اس کے بعد پھر کبھی اپنے بھائی کی وفات پر اس طرح غم
کا اظہار
نہیں کیا ہے
پھر اس زمانہ میں ایمان لانے والوں میں سے ایک عبد اللہ بن ام مکتوم تھے جو نابینا تھے اور حضرت
خدیجہ کے عزیزوں میں سے تھے.اُن کے متعلق ایک دلچسپ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ کو جو قریش کا ایک بہت معزز رئیس تھا نہایت شوق اور سرگرمی سے تبلیغ فرما
رہے تھے ابن ام مکتوم جلدی جلدی آئے اور کسی دینی مسئلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ
دریافت کرنا چاہا لیکن اپنے شوق میں انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ یہاں کن لوگوں کا مجمع ہے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مصروف ہیں اور آداب مجلس رسول کے ماتحت ان کو ایسے حالات میں کیا کرنا
چاہیئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع کے لحاظ سے اُن کا یہ فعل پسند نہ آیا اور آپ کے چہرہ پر
نا پسندیدگی کے آثار ظاہر ہوئے مگر آپ کے اخلاق کریمانہ کا یہ تقاضا تھا کہ آپ نے اُن کو زبان سے
کچھ نہیں فرمایا بلکہ صرف آپ نے یہ کیا کہ اُن کی طرف سے بے التفاتی کر کے ولید سے اپنی بات جاری
ل : زرقانی و خمیس
: اسد الغابه
Page 163
۱۴۸
رکھی.عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنی غلطی کی طرف تو خیال نہیں گیا مگر آپ کی اس بے التفاتی پر ملال ہوا اور
انہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ولید ایک بڑا آدمی ہے اس لیے آپ نے شاید اس کے مقابلہ میں مجھ
غریب کی پروا نہیں کی.حالانکہ یہ خیال بالکل غلط اور بے بنیاد تھا کیونکہ اس وقت غریب امیر کا کوئی سوال
نہ تھا بلکہ آپ ایک ایسے شخص کو تبلیغ فرمانے میں مصروف تھے جس کو ان باتوں کے سنے کا بہت کم موقع ملتا تھا
اور ابن ام مکتوم کے لیے یہ موقع ہر وقت میسر تھا اس لیے آپ نے اس موقع کو ہاتھ سے دینا پسند نہ فرمایا
اور ابن ام مکتوم کے قطع کلام کو بُرامانا جو حقیقت میں تھا بھی آداب مجلس کے خلاف.مگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کو ابن ام مکتوم کے دلی ملال پر اطلاع ہوئی اور ایک
قرآنی وحی بھی اس بارے میں نازل ہوئی تو آپ نے اُن کی بڑی دلداری کی اور عرب کے طریق کے
مطابق اپنی چادر مبارک بچھا کر اس پر ان کو بٹھایا ہے
پھر اس زمانہ میں مسلمان ہونے والوں میں ایک جعفر بن ابی طالب تھے جو حضرت علیؓ کے حقیقی بھائی
تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز تھے.جعفر کے متعلق مؤرخین لکھتے ہیں کہ خلق اور خلق
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے.پھر عمار بن یاسر تھے جو قبیلہ مذحج سے تھے اور اپنے
باپ یا سر اور والدہ سمیہ کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے.پھر صہیب بن سنان تھے جو عام طور پر صہیب رومی
کے نام سے مشہور ہیں مگر دراصل وہ رومی نہ تھے بلکہ کسی زمانہ میں جبکہ ان کا باپ ایرانی حکومت کی طرف
سے کسی جگہ کا عامل تھا رومیوں کے ہاتھ قید ہو کر غلام بنا لیے گئے تھے اور پھر کچھ مدت تک اُن میں بطور غلام
مقیم رہے بالآ خر عبداللہ بن جدعان قرشی نے جو ملکہ کا ایک رئیس تھا انہیں خرید کر آزاد کر دیا تھا.صہیب
جب مسلمان ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال کے طور پر فرمایا کہ یہ ہمارا پہلا رومی پھل
ہے.صہیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اتنے دلدادہ تھے کہ جب یہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو قریش نے ان کو روکا کہ تو ہمارے اندر ایک
غریب غلام کی حیثیت میں آیا تھا اور اب تو ہم میں رہ کر امیر ہو گیا ہے اس لیے ہم تجھے نہیں جانے دیتے.انہوں نے کہا.تم میری ساری دولت لے لو اور مجھے جانے دو.اس شرط پر قریش نے انہیں جانے دیا.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ نے خوشی کے ساتھ فرمایا کہ:
صہیب نے بہت نفع والی تجارت کی ہے.جب حضرت عمر اپنے عہد خلافت میں مہلک طور پر
له : قرآن شریف سورۃ عبس :۲ و تفسیر ابن جرير سورة مذکور واسد الغابه
Page 164
۱۴۹
زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنی جگہ صہیب کو ہی جو اس وقت پاس موجود تھے امام الصلوۃ مقرر فرمایا
تھا.چنانچہ حضرت عمر کا جنازہ بھی صہیب نے پڑھا تھا.ابو موسی اشعری بھی غالباً اُسی زمانہ میں یا اس
کے قریب مسلمان ہوئے تھے.ابو موسی" یمن کے رہنے والے تھے اور نہایت خوش الحان تھے.حتی کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے متعلق ایک دفعہ فرمایا کہ ابو موسیٰ کو تو لحن داؤدی سے حصہ ملا
ہے.یہ وہی ابو موسیٰ ہیں جو حضرت علی کے عہد خلافت میں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان ثالث
مقرر ہوئے تھے.قریش کی مخالفت کا آغاز اور اس کے اسباب جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے دار ارقم میں
داخل ہونے کے زمانہ سے کچھ پہلے ہی کھلم
کھلی تبلیغ شروع ہو گئی تھی اور مکہ کے گلی کوچوں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تھا.قریش اب تک تو ایک حد
تک خاموش تھے لیکن اب ان کو بھی فکر شروع ہوا کہ کہیں یہ مرض زیادہ نہ پھیل جاوے اور اسلام کا پودا
مکہ کی زمین میں جڑ نہ پکڑ جاوے.اس لیے اب انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ شروع کی اور اسلام کی
اشاعت کو بزور روکنا چاہا.اس مخالفت کے کیا اسباب تھے؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں کچھ زیادہ لکھنے
کی ضرورت نہیں ہے.ہر نیا الہی سلسلہ جو دنیا میں قائم ہوتا ہے دنیا کی طرف سے ضرور اس کی مخالفت ہوتی
ہے کیونکہ وہ لازماً اپنے اندر ایسی باتیں رکھتا ہے جس سے اس وقت کی دنیا محض نا آشنا ہوتی ہے بلکہ یہ
وہ باتیں ہوتی ہیں جن کو دنیا اپنی موجودہ عادات اور موجودہ عقائد و خیالات کے واسطے ایک یقینی موت
سمجھتی ہے.درحقیقت انبیاء کی بعثت ہی ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ جب دنیا کے لوگ اس راستہ کو
چھوڑ چکے ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ وہ چلیں اور وہ اپنے موجودہ غلط راستہ کو ہی صحیح راستہ
سمجھ رہے ہوتے ہیں.پس جب بھی کبھی کوئی نیا نبی آتا اور دُنیا کوسید ھے راستے کی طرف بلاتا ہے تو
دنیا اس کی باتوں کو غلط خیال کرتی اور اس کے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتی ہے؛ چنانچہ قرآن شریف
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
يُحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُ ونَ
د یعنی وائے حسرت لوگوں پر کہ کوئی بھی رسول اُن کی طرف ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ
انہوں نے ہنسی اور ٹھٹھا نہ کیا ہو.“
ل : سورۃ لیس : ۳۱
Page 165
۱۵۰
اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ بڑے سمجھے جاتے ہیں وہی عموماً مخالفت میں بھی بڑھے ہوئے
ہوتے ہیں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكْبِرَ مُجْرِ مِنْهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا
د یعنی سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ ہر جگہ رسول کے مقابلہ پر بڑے لوگ ہی
خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے والے اور فتنہ وفساد کے بانی بن جاتے ہیں.“
چنانچہ دیکھ لو حضرت ابراہیم مبعوث ہوئے تو اُن کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے اُن کو پکڑ کر آگ
میں جھونک دیا.حضرت موسی آئے تو ان کو بھی اکا بر قوم کی طرف سے جنگ و جدل کے مصائب دیکھنے
پڑے.حضرت مسیح کی باری آئی تو اُن کی قوم کے علماء اور فریسیوں نے مل ملا کر اُن کو دار پر کچھوا دیا.ہندوستان میں کرشن مبعوث ہوئے تو اُن کی قوم ان کو ہلاک کرنے کے لیے اُٹھ کھڑی ہوئی.تو کیا سرور
انبیاء اس سنت رسل سے باہر رہتا؟ نہیں بلکہ جتنا عظیم الشان مشن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے
تھے اتنی ہی شدید آپ کی مخالفت ہونی چاہئے تھی کیونکہ آپ ایسے زمانہ میں مبعوث ہوئے تھے کہ جب
تاریکی کا خاص زور تھا اور ضروری تھا کہ نور کے آنے پر تاریکی کی فوجیں اپنی انتہائی طاقت کے ساتھ اس کا
مقابلہ کریں؛ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سارے گذشتہ انبیاء کی نسبت آپ کی مخالفت سب سے زیادہ ہوئی.اور اس مخالفت کے موٹے موٹے ظاہری اسباب یہ تھے:
(1) قریش ایک پرلے درجہ کی بت پرست قوم تھی اور بتوں کی عزت و محبت ان کے دلوں میں
اس قدر جمی ہوئی تھی کہ اُن کے خلاف ایک لفظ بھی سننا اُنہیں گوارا نہ تھا.خانہ کعبہ جو محض اللہ تعالیٰ کی
عبادت کے واسطے بنایا گیا تھا اس میں بھی ان ظالموں نے سینکڑوں بت جمع کر رکھے تھے اور اپنی تمام
ضروریات کے لیے انہی بتوں کا منہ تکتے تھے.اب اسلام آیا تو اس کا بنیادی اصول ہی تو حید باری تعالیٰ
تھا اور صاف حکم تھا کہ کسی انسان یا درخت یا پتھر یا ستارے وغیرہ کے سامنے سرمت جھکاؤ بلکہ:
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ :
صرف اسی ذات کے سامنے جھکو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے.“
پھر یہی نہیں بلکہ قریش کے بتوں کو اُن کے خیال میں ہتک آمیز لفظوں میں یاد کیا جاتا تھا اور ان کو
جہنم کا ایندھن قرار دیا جاتا تھا.جیسے مثلاً فر مایا:
ل : سورة انعام : ۱۲۴
۲ : سورة حم سجده : ۳۸
Page 166
۱۵۱
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ يا
د یعنی اے لوگو! تم اور تمہارے وہ بت جن کو تم پوجتے ہو دوزخ کا ایندھن ہیں.“
ان باتوں نے قریش کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی اور وہ ایک جان ہو کر اسلام کو مٹانے کے
واسطے اُٹھ کھڑے ہوئے.(۲) بت پرستی کے علاوہ عرب میں عادات اور اخلاق کا جو حال تھا وہ اس کتاب کے شروع میں
بیان ہو چکا ہے.زنا، شراب، قمار بازی، غارت گری قبل ، حرام خوری کا بازار ہر وقت گرم رہتا تھا مگر
اسلام ان سب باتوں سے روکتا تھا.گویا اسلام لانے سے ان کو ایک نئی زندگی اختیار کرنی پڑتی تھی اور
قریش اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے.یہی حال رسوم پرستی کا تھا جو گویا عربوں کے دین و مذہب کا جزو
بن چکی تھیں مگر اسلام سب گندی اور خلاف اخلاق اور خلاف مذہب رسوم کو پاؤں کے نیچے مسلتا تھا.(۳) اپنے آبا ؤ اجداد کی عزت اور ہر بات میں خواہ وہ درست ہو یا غلط ان کی پیروی اختیار کرنا
عربوں کے دین و مذہب کا جز و تھا.اسی وجہ سے اُن کو اصرار تھا کہ:
بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا :
پایا ہے.“
یعنی ہم تو بہر حال اُسی بات کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو
مگر اسلام خدا دا د عقل کو سچ اور جھوٹ کے درمیان حکم قرار دیتا تھا اور اُن کے مشرک آباء کے
متعلق صاف کہتا تھا:
اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ -
کیا وہ اپنے آباؤ اجداد ہی کی اتباع کریں گے خواہ ان کے آباء گمراہ اور بیوقوف ہی
66
کیوں نہ ہوں.“
(۴) قریش ایک نہایت متکبر قوم تھی.یہ لوگ کسی کو اپنے برابر نہ سمجھتے تھے اور غلاموں کو تو
خصوصیت سے ذلیل اور زیر رکھنا چاہتے تھے.مگر اسلام حقوق کے معاملہ میں ان سب امتیازات کو مٹا کر
ایک عالمگیر اخوت قائم کرتا اور آقا اور غلام کو خدا تعالیٰ کے حضور میں ایک صف میں کھڑا کرتا تھا اور یہ بات
رؤسائے قریش کے واسطے موت کے پیالہ سے کم بیتھی.ا : سورۃ انبیاء : ۹۹ ے : سورۃ بقرہ : ۱۷۱
ے : سورۃ بقرہ : ۱۷۱
Page 167
۱۵۲
(۵) قریش میں بڑے بڑے صاحب اثر اور مالدار لوگ موجود تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
با وجود ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کے ان دونوں باتوں سے خالی تھے.یعنی نہ تو آپ اپنی خلوت پسند
طبیعت کی وجہ سے لیڈران قریش میں سے تھے اور نہ مال و دولت کے لحاظ سے کوئی ممتاز حیثیت رکھتے
تھے.ایسی حالت میں سردارانِ مکہ کے لیے آپ کی اتباع اختیار کرنا ایک ایسی بڑی قربانی تھی جس کے
لیے یہ لوگ ہر گز تیار نہیں تھے اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ :
لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ O
کیوں نہ یہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر نازل ہوا.“
(1) ان اسباب کے علاوہ ایک باعث یہ بھی تھا کہ قریش کے مختلف قبائل کے درمیان سخت
رقابت اور دشمنی رہتی تھی اس لیے باقی قبائل کو ہر گز یہ گوارا نہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ
اُن پر کسی قسم کا امتیاز لے جاوے اور قبائل بنوامیہ اور بنومخزوم کو تو خصوصیت سے بنو ہاشم کے ساتھ سخت
عداوت تھی.اسی لیے سب قبائل سے بڑھ کر ان دو قبائل نے اسلام کی مخالفت میں حصہ لیا.ائمة الكفر قریش میں سے جن لوگوں نے اسلام کی زیادہ مخالفت کی اور اس تحریک میں وہ دوسروں
کے لیڈر سمجھے جاتے تھے وہ سب ایک قسم کے نہ تھے بعض میں ذاتی شرافت تھی اور وہ اپنے
رنگ میں بالعموم شرافت ہی کا معاملہ کرنا چاہتے تھے مگر کچھ تو اپنی بڑائی کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت قبول نہ کر سکتے تھے اور کچھ انہیں یہ دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی کہ اس طرح بعض ” خام خیالوں“
کے ہاتھ سے اُن کے دین آبائی کی بربادی ہو رہی ہے اُن میں زیادہ ممتاز یہ لوگ نظر آتے ہیں.اول مطعم بن عدی جو قبیلہ بنو نوفل سے تھا اور رؤساء قریش میں سے تھا.مطعم رکا مشرک تھا مگر معاملات
میں حتی الوسع شرافت کا طریق اختیار کرتا تھا؛ چنانچہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے خلاف قریش کے معاہدہ بائیکاٹ کو توڑنے اور سفر طائف سے واپسی پر آپ کو اپنی پناہ میں
مکہ میں داخل کرنے میں مطعم نے خاص شرافت اور خاص جرات سے کام لیا تھا.دوسرے ابوالبختری تھا
جو قبیلہ بنو اسد سے تھا.ابو البختری بھی مخالفت میں حتی الوسع شرافت کو ہاتھ سے نہیں دیتا تھا.اسی
ذیل میں ایک شخص زبیر بن ابو امیہ تھا جو حضرت اُم سلمہ کا بھائی تھا اور با وجود مخالفت کے عموماً شرافت
کا پہلو اختیار کرتا تھا.: سورۃ زخرف : ۳۲
Page 168
۱۵۳
دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جن کی مخالفت کچھ شرارت کا پہلو بھی لیے ہوئے تھی.ان میں یہ لوگ ممتاز
تھے.اول عقبہ بن ربیعہ جو بنو عبد شمس میں سے تھا اور بہت مالدار اور صاحب اثر تھا.جنگ بدر کے موقع پر
جب عقبہ اپنے سُرخ اُونٹ پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے سامنے آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے
دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس گروہ میں کسی میں کچھ شرافت ہے، تو اس سُرخ اونٹ کے سوار میں ہے.عقبہ کا بھائی
شیبہ بھی اسی کے زیر اثر تھا.یہ دونوں جنگ بدر میں حضرت حمزہ اور حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے.دُوسرے ولید بن مغیرہ تھا جو حضرت خالد بن ولید کا والد اور قریش کا رئیس اعظم تھا.حتی کہ قریش اسے
اپنا باپ سمجھتے تھے.ولید ہجرت نبوی کے تین ماہ بعد اتفاقی طور پر تیر چبھ جانے سے ہلاک ہوا.تیسرے
عاص بن وائل سہمی تھا.جو حضرت عمرو بن عاص کا باپ تھا.یہ بھی نہایت دولت مند اور بڑا صاحب اثر
تھا.عاص ہجرت کے دوسرے ماہ پاؤں سوج جانے سے نہایت تکلیف اُٹھا کر مکہ میں مر گیا.تیسری قسم کے گروہ کی حالت بالکل مختلف تھی.یہ وہ لوگ تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت
میں بالکل اندھے ہو رہے تھے اور ہر جائز و ناجائز طریق سے کوشش کرتے تھے کہ اسلام اور بانی اسلام کو
صفحہ دنیا سے مٹادیں اور مسلمانوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں اور قریش میں انہی لوگوں کا زیادہ زور
تھا اور انہی لوگوں کی کثرت تھی.اُن میں خاص طور پر ممتاز یہ لوگ نظر آتے ہیں.اول عمر و بن ہشام جو
بنو مخزوم میں سے تھا.یہ وہ شخص ہے جسے گو یار اس المعاندین سمجھنا چاہئے.قریش میں یہ نہایت ممتاز حیثیت
رکھتا تھا اور وہ اسے ابو الحکم یعنی ” دانائی کا باپ کہتے تھے.مگر مسلمانوں نے اس کا نام ابوجہل رکھا.یہ
جنگ بدر میں دو انصار لڑکوں کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا.دوسرے ابولہب بن عبدالمطلب جو بنو ہاشم
میں سے تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چا تھا.ابولہب مخالفت اور ایذاء رسانی میں ابو جہل کا
ہم پلہ تھا اور اسے یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ معاندین اسلام میں سے صرف اس کا نام قرآن شریف
میں صراحت کے ساتھ مذکور ہوا ہے.ابولہب جنگ بدر سے تھوڑا عرصہ بعد مکہ میں بیمار پڑ کر ہلاک ہوا.تیسرے عقبہ بن ابی معیط تھا جو بنوامیہ میں سے تھا اور پرلے درجہ کا شریر اور بد باطن شخص تھا.یہ جنگ بدر
میں شریک ہوا اور مارا گیا.پھر امیہ بن خلف تھا جو بنو نجح میں سے تھا.شرارت اور عداوت میں یہ ابو جہل کا
مثل تھا.جنگ بدر میں قتل ہوا.امیہ کا بھائی ابی بن خلف بھی اسی قماش کا آدمی تھا.یہ جنگ اُحد میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زخمی ہوا اور اسی زخم سے اپنی کیفر کردار کو پہنچا.پھر النضر بن الحارث
تھا جو بنو عبد الدار میں سے تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دُکھ دیا کرتا تھا.یہ جنگ بدر میں قید ہوا
Page 169
۱۵۴
اور اپنے جرموں کی پاداش میں مارا گیا.پھر اسود بن عبد یغوث ، حارث بن قیس، اسود بن مطلب، ابوقیس
بن فاکہد ، منبہ بن الحجاج ، نبیه بن الحجاج ، مالک بن طلاطلہ، حکم بن ابی العاص ، رکانہ بن یزید وغیرہ بھی
شرارت اور عداوت میں کم و بیش بہت حصہ لیتے تھے یا
ان کے علاوہ بعض اور لوگ بھی تھے جو عداوت میں بہت بڑھے ہوئے تھے لیکن چونکہ وہ بعد میں
مسلمان ہو گئے اس لئے ان کا اس جگہ اس فہرست میں ذکر کرنا شاید درست نہ ہو البتہ اپنے اپنے موقع پر
اُن کا ذکر خود آ جائے گا.اسلام اور بانی اسلام کے خلاف کفار مکہ کی عداوت اسلام کے خلاف جب قریش کی
مخالفت شروع ہوئی تو پھر وہ دن بدن
بڑھتی گئی اور خطرناک صورت اختیار کرتی گئی ؛ چنانچہ سرولیم میورلکھتا ہے کہ قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ:
یہ نیا مذہب صفحہ دنیا سے ملیا میٹ کر دیا جاوے اور اس کے متبعین اس سے بزور روک
دیئے جاویں اور قریش کی طرف سے جب ایک دفعہ مخالفت شروع ہوئی تو پھر دن بدن اُن کی
ایذاء رسانی بڑھتی اور آتش غضب تیز ہوتی گئی.“
در حقیقت جوفتنہ مخالفین اسلام نے اسلام کے خلاف بر پا کیا اور اس کے مٹانے کے واسطے جو جو
تدا بیر کیں وہ ایک لمبی اور دردناک کہانی ہے جس کا سلسلہ ہجرت کے آٹھویں سال تک پہنچتا ہے.ابو طالب کے پاس قریش کا پہلا وفد سب سے دیہی
سب سے پہلی کوشش قریش کی یہ تھی کہ جس طرح بھی ہو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی ہمدردی اور
حفاظت سے محروم کر دیں.کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک ابوطالب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ہیں اس وقت تک وہ بین القبائل تعلقات کو خراب کئے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہاتھ
نہیں اُٹھا سکتے.ابو طالب قبیلہ بنو ہاشم کے رئیس تھے اور باوجو د مشرک ہونے کے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے مربی اور محافظ تھے اس لیے ان کے ہوتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہاتھ
اُٹھانا بین القبائل سیاست کی رُو سے بنو ہاشم کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے مترادف تھا جس کے لیے
دوسرے قبائل قریش ابھی تک تیار نہ تھے.لہذا پہلی تجویز اُنہوں نے یہ کی کہ ابو طالب کے پاس
دوستانہ رنگ میں ایک وفد بھیجا کہ وہ اپنے بھتیجے کو اشاعت اسلام سے روک دیں؛ چنانچہ ولید بن مغیرہ،
له : تاریخ کامل وزرقانی
: میور صفحه ۶۱
Page 170
۱۵۵
عاص بن وائل ، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابوسفیان وغیرہ جو سب رؤساء قریش میں سے تھے
ابوطالب کے پاس آئے اور نرمی کے طریق پر کہا کہ آپ ہماری قوم میں معزز ہیں.اس لیے ہم آپ سے
درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس نئے دین کی اشاعت سے روک دیں اور یا پھر اس کی
حمایت سے دستبردار ہو جاویں اور ہمیں اور اس کو چھوڑ دیں کہ ہم آپس میں فیصلہ کر لیں.ابو طالب نے
اُن کے ساتھ بہت نرمی کی باتیں کیں اور اُن کے غصہ کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بالآخر انہیں
دوسرا وفد
ٹھنڈا کر کے واپس کر دیا ہے
لیکن چونکہ اُن کی ناراضگی کا سبب موجود تھا بلکہ دن بدن ترقی کرتا جاتا تھا اور قرآن شریف
میں بڑی سختی سے شرک کے رد میں آیات نازل ہو رہی تھیں.اس لیے کوئی لمبا عرصہ نہ
گذرا تھا کہ یہ لوگ پھر ابو طالب کے پاس جمع ہوئے اور ان سے کہا کہ اب معاملہ حد کو پہنچ گیا ہے اور ہم کو
رجس اور پلید اور شتر البریہ اور سفہاء اور شیطان کی ذریت کہا جاتا ہے اور ہمارے معبودوں کو جہنم کا
ایندھن قرار دیا جاتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو لا یعقل کہہ کر پکارا جاتا ہے.اس لیے اب ہم صبر نہیں
کر سکتے اور اگر تم اس کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تو پھر ہم بھی مجبور ہیں.ہم پھر تم سب کے ساتھ
مقابلہ کریں گے حتی کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ہلاک ہو جاوے.“ ابو طالب کے لیے اب نہایت
نازک موقع تھا اور وہ سخت ڈر گئے اور اُسی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا یا.جب آپ آئے تو اُن
سے کہا کہ ”اے میرے بھتیجے ! اب تیری باتوں کی وجہ سے قوم سخت مشتعل ہوگئی ہے اور قریب ہے کہ تجھے
ہلاک کر دیں اور ساتھ ہی مجھے بھی.تو نے ان کے عقلمندوں کو سفیہ قرار دیا.اُن کے بزرگوں کوشر البریۃ
کہا.ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جہنم اور وقود النار رکھا اور خود انہیں رجس اور پلید ٹھہرایا.میں تجھے خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ اس دُشنام دہی سے اپنی زبان کو تھام لو اور اس کام سے باز آ جاؤ ؛ ورنہ
میں تمام قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب ابو طالب کا
پائے ثبات بھی لغزش میں ہے اور دنیاوی اسباب میں سے سب سے بڑا سہارا مخالفت کے بوجھ کے نیچے
دب کر ٹوٹا چاہتا ہے.مگر آپ کے ماتھے پر بل تک نہ تھا.نہایت اطمینان سے فرمایا.’ چا یہ دشنام دہی
نہیں ہے بلکہ نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے اور یہی تو وہ کام ہے جس کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں کہ
لوگوں کی خرابیاں اُن پر ظاہر کر کے انہیں سیدھے رستے کی طرف بلاؤں اور اگر اس راہ میں مجھے مرنا
ل : ابن ہشام
Page 171
ܪܬܙ
در پیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں.میری زندگی اس راہ میں وقف ہے اور میں
موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا اور اے چچا! اگر آپ کو اپنی کمزوری اور تکلیف کا خیال
ہے تو آپ بے شک مجھے اپنی پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جاویں.مگر میں احکام الہی کے پہنچانے سے
کبھی نہیں رکوں گا اور خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر
دے دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں رہوں گا اور میں اپنے کام میں لگا رہوں گاحتیٰ کہ خدا اسے
پورا کرے یا میں اس کوشش میں ہلاک ہو جاؤں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر فرمارہے تھے اور
آپ کے چہرہ پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں تھی اور جب آپ تقریر ختم کر چکے تو آپ
یکلخت چل پڑے اور وہاں سے رُخصت ہونا چاہا مگر ابو طالب نے پیچھے سے آواز دی.جب آپ کوٹے تو
آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کے آنسو جاری تھے.اس وقت ابوطالب نے بڑی رقت کی آواز میں آپ
سے مخاطب ہو کر کہا.” بھیجے جا اور اپنے کام میں لگارہ جب تک میں زندہ ہوں اور جہاں تک میری طاقت
ہے میں تیرا ساتھ دوں گا."
166
تیسر اوفد جب اس دفعہ بھی قریش ناکام رہے تو انہوں نے ایک اور چال چلی اور وہ یہ کہ قریش کے
ایک اعلیٰ خاندان سے ایک ہونہار نو جوان عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس
گئے اور کہنے لگے کہ ہم عمارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لائے ہیں اور تم جانتے ہو کہ یہ قریش کے بہترین
نوجوانوں میں سے ہے.پس تم ایسا کرو کہ محمد کے عوض میں تم اس لڑکے کو لے لو اور اس سے جس طرح
چاہو فائدہ اُٹھاؤ اور چاہو تو اسے اپنا بیٹا بنا لو.ہم اس کے حقوق سے کلیۂ دستبردار ہوتے ہیں اور اس
کے عوض تم محمد کو ہمارے سپرد کر دو جس نے ہمارے آبائی دین میں رخنہ پیدا کر کے ہماری قوم میں ایک فتنہ
کھڑا کر رکھا ہے.اس طرح جان کے بدلے جان کا قانون پورا ہو جائے گا اور تمہیں کوئی شکایت نہیں
ہوگی.ابو طالب نے کہا.یہ عجیب انصاف ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو لے کر اپنا بیٹا بناؤں اور اسے
کھلاؤں اور پلاؤں اور اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قتل کر دو.واللہ یہ کبھی نہیں ہوگا.قریش کی
طرف سے مطعم بن عدی نے کہا کہ ”پھر اے ابو طالب ! تمہاری قوم نے تو تم پر ہر رنگ میں حجت پوری کر
دی ہے اور اب تک جھگڑے سے اپنے آپ کو بچایا ہے مگر تم ان کی کوئی بات بھی مانتے نظر نہیں آئے.“
ابوطالب نے کہا.”واللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جارہا اور مطعم میں دیکھتا ہوں کہ تم بھی اپنی قوم کی
لے ازالہ اوہام جلد ۱ صفحه ۱۰ وابن ہشام وزرقانی
Page 172
۱۵۷
پیٹھ ٹھونکنے میں میرے ساتھ بے وفائی کرنے پر آمادہ ہو.پس اگر تمہارے تیور بدلے ہوئے ہیں تو میں کیا
کہ سکتا ہوں.تم نے جو کرنا ہو وہ کرو.،،
مسلمانوں کے متعلق قریش کا فیصلہ رؤساء قریش ابو طالب کی طرف سے مایوس ہو گئے تو
انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے سے
پہلے یہ تجویز کی کہ جس جس قبیلہ میں سے کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھاوہ قبیلہ اپنے اپنے آدمی پر دباؤ ڈال کر
اسے اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرے؛ چنانچہ سب نے مل کر باہم مشورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ
نومسلموں پر ان کے اپنے اپنے قبیلہ کی طرف سے زور ڈالا جائے تاکہ کسی قسم کی بین القبائل پیچیدگی نہ
پیدا ہو اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب خود مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے تو آپ
اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے اور یہ سارا کھیل بگڑ جائے گا.اس فیصلہ میں یہ بھی قرار پایا کہ صرف زبانی دباؤ
تک نہ رہا جائے بلکہ ہر رنگ میں تنگ کر کے اور تکلیف میں ڈال کر نو مسلموں کو واپس لانے کی کوشش کی
جائے.جب ابو طالب کو اس مشورہ سے اطلاع ہوئی تو انہوں نے بھی ایک جوابی تدبیر کے طور پر بنو ہاشم
اور بنو مطلب کو ایک جگہ جمع کیا اور حالات بتا کر تحریک کی کہ اس عداوت کے طوفان میں ہمیں محمد کی حفاظت
کرنی چاہئے چنانچہ ابولہب کے سوا جو اسلام کی عداوت میں اندھا ہورہا تھا باقی سب نے اس تجویز سے
اتفاق کیا اور قومی غیرت میں آکر دوسروں کے مقابلہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کے لئے تیار
ہو گئے..ان حالات نے مکہ کی فضا میں ایک آتشی مادہ پیدا کر دیا تھا.مگر چونکہ ابھی تک مسلمانوں کی
ایذارسانی کا فیصلہ ہر قبیلہ کی حدود کے اندر محدود تھا، اس لئے کوئی بین القبائل پیچیدگی پیدا نہیں ہوئی.ہاں مسلمانوں کے لئے انفرادی طور پر سخت مصائب و آلام کا دروازہ کھل گیا اور اس وقت سے لے کر
ہجرت میثرب تک کی داستان ایک خون کے آنسور لانے والی داستان ہے.مسلمانوں کی تکالیف کا نمونہ ان ایام میں جو جو تکالیف مسلمانوں کو پہنچیں اُن کو وہی جانتے تھے
جن کو یہ مصائب جھیلنے پڑے.مگر ہاں تاریخ نے جہاں تک ان
واقعات کو محفوظ رکھا ہے اور وہ یقیناً اصل واقعات سے بہت کم ہیں.ان کا نمونہ درج ذیل ہے:
حضرت عثمان بنوامیہ میں سے تھے اور ایک نسبتاً پختہ عمر کے اور مرفہ الحال آدمی تھے، لیکن قریش کے
مذکورہ بالا فیصلہ کے بعد اُن کے چا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسیوں سے باندھ کر پیٹا اور ان بیچاروں
P
ل : ابن ہشام وطبری
: ابن ہشام وطبری
Page 173
۱۵۸
ย
نے سامنے سے اُف تک نہیں کی یا زبیر بن العوام قبیلہ اسد سے تھے اور ایک جوانمرد آدمی تھے مگر ان کا
ظالم چا اُن کو چٹائی میں لپیٹ کر اُن کے ناک میں آگ کا دھوآں دیا کرتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاویں
مگر وہ بڑی خوشی کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرتے اور کہتے کہ میں صداقت کو پہچان کر پھر انکار نہیں کر
سکتا ہے سعید بن زید جو حضرت عمرؓ کے بہنوئی تھے بنو عدی سے تھے اور اپنے حلقہ میں معزز تھے، لیکن جب
عمر بن الخطاب کو ان کے اسلام کا علم ہوا تو وہ انہیں گرا کر ان کی چھاتی پر سوار ہو گئے اور اسی کش مکش میں اپنی
بہن کو بھی زخمی کر دیا.عبد اللہ بن مسعود جو قبیلہ ھذیل میں سے تھے انہیں قریش نے عین صحن کعبہ میں
مار مار کر ہلکان کر دیا.ابوذرغفاری کو قریش نے اتنا پیٹا کہ مارتے مارتے زمین پر بچھا دیا اور قریب تھا
کہ جان سے مار ڈالتے ، مگر عباس بن عبدالمطلب نے یہ کہہ کر ان کو قریش سے چھڑایا کہ ” جانتے ہو کہ یہ
شخص بنو غفار میں سے ہے جو تمہارے شامی تجارت کے راستہ پر آباد ہیں.اگر اُن کو علم ہوا تو تمہارا راستہ
روک دیں گے.یہ سختیاں اُن لوگوں پر تھیں جو طاقتور قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ، مگر جو حال غلاموں اور
دوسرے کمزور لوگوں کا تھا وہ پڑھ کر تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں.ذیل کی چند مثالیں قریش کے
مظالم کا صرف ایک معمولی نمونہ ہیں.بلال بن رباح اُمیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے.اُمیہ ان کو دو پہر کے وقت جبکہ اوپر سے
آگ برستی تھی اور مکہ کا پتھر یلا میدان بھٹی کی طرح پیا تھا ، باہر لے جاتا اور ننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا اور
بڑے بڑے گرم پتھر اُن کے سینے پر رکھ کر کہتا لات اور عُزّی کی پرستش کر اور محمد سے علیحدہ ہو جاورنہ
اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا.بلال زیادہ عربی نہ جانتے تھے.بس صرف اتنا کہتے اَحد اَحد یعنی
اللہ ایک ہی ہے.اللہ ایک ہی ہے.اور یہ جواب سن کر اُمیہ اور تیز ہو جاتا اور ان کے گلے میں رستہ ڈال کر
انہیں شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو مکہ کی پتھر یلے گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے جس سے اُن کا
بدن خون سے تر بتر ہو جاتا.مگر اُن کی زبان پر سوائے اَحد اَحد کے اور کوئی لفظ نہ آتا.حضرت ابوبکر نے
اُن پر یہ جور و ستم دیکھے تو ایک بڑی قیمت پر خرید کر انہیں آزاد کر دیا.ابو فکیه صفوان بن امیہ کے غلام تھے.ان کو بھی یہ لوگ اسی طرح گرم زمین پر لٹا دیتے اور سینے پر
اتنے بھاری پتھر رکھتے کہ اُن کی زبان باہر نکل آتی.طبقات ابن سعد حالات عثمان بن عفان
ے : ابن ہشام ذکر اسلام عمر
ے : زرقانی جلدا باب اول من اسلم
: اسد الغابه ه : بخاری باب قصہ اسلام ابی ذر
Page 174
۱۵۹
عامر بن فہیرہ بھی ایک غلام تھے انہیں بھی اسلام کی وجہ سے سخت تکالیف دی جاتی تھیں.ان کو
حضرت ابو بکر نے خرید کر اپنے پاس بکریاں چرانے پر نو کر رکھ لیا.لبینہ بوعدی کی لونڈی تھی.اسلام لانے سے پہلے عمر اس کو اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے ،
لیکن جب ذرا دم لے لیتے تو پھر اُسی طرح مارنا شروع کر دیتے وہ سامنے سے صرف اتنا کہتی کہ عمرا اگر تم
نے اسلام قبول نہ کیا تو خدا اس ظلم کو بے انتقام نہیں چھوڑے گا.زنیرہ بنومخزوم کی لونڈی تھی.ابو جہل نے اُسے اس بے دردی سے پیٹا کہ اس کی آنکھیں جاتی
رہیں.ابوجہل اس کی طرف اشارہ کر کے طنزاً کہا کرتا تھا کہ اگر اسلام سچا ہوتا تو کیا بھلا اسے مل جاتا
اور ہم محروم رہتے.صہیب بن سنان رومی ہر چند کہ اب غلام نہ تھے اور تھے بھی نسبتاً خوشحال لیکن قریش ان کو اتنا پیٹتے
کہ اُن کے حواس مختل ہو جاتے.یہ وہی صہیب ہیں جن کو حضرت عمر نے زخمی ہونے پر امام الصلوۃ مقرر
کیا تھا اور انہوں نے ہی حضرت عمر کا جنازہ پڑھایا تھا یا
خباب بن الارت بھی اب غلام نہ تھے بلکہ آزاد تھے اور لوہار کا کام کرتے تھے ،مگر ایک دفعہ قریش
نے اُن کو پکڑ کر انہی کی بھٹی کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر الٹالٹا دیا اور ایک شخص اُن کی چھاتی پر چڑھ گیا، تا کہ
کروٹ نہ بدل سکیں؛ چنانچہ وہ کوئلے اُسی طرح جل جل کر اُن کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے.خباب نے
مدتوں کے بعد حضرت عمرؓ سے یہ واقعہ بیان کیا اور اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی جو زخموں کے داغوں سے بالکل
سفید تھی.خباب کے متعلق یہ روایت بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ مکہ کے ایک رئیس عاص بن وائل نے اُن
سے کچھ تلوار میں بنوائیں اور جب خباب نے قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ
جنت میں انسان کو ہر قسم کی نعمت سونا اور چاندی وغیرہ سب حسب خواہش ملے گی.سو تم اپنی تلواروں کی
قیمت مجھ سے جنت میں آکر لے لینا.کیونکہ واللہ اگر تمہیں جنت میں جانے کی توقع ہے تو مجھے تو بدرجہ اولیٰ
ہونی چاہئے اور یہ کہہ کر قیمت دینے سے انکار کر دیا ہے
عمار اور ان کے والد یا سر اور ان کی والدہ سمیہ کو بنی مخزوم جن کی غلامی میں سمیہ کسی وقت رہ چکی
تھیں اتنی تکالیف دیتے تھے کہ ان کا حال پڑھ کر بدن پر لرزہ پڑنے لگتا ہے.ایک دفعہ جب ان فدائیانِ
اسلام کی جماعت کسی جسمانی عذاب میں مبتلا تھی اتفاقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرف آ نکلے.ل : اسد الغابہ و تاریخ کامل
بخاری ومسلم بحوالہ تلخیص الصحاح جلدا صفحه ۲۰۶
Page 175
17.آپ نے اُن کی طرف دیکھا اور دردمندانہ لہجہ میں فرمایا: صَبرًا إِلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ
”اے آل یا سر صبر کا دامن نہ چھوڑنا کہ خدا نے تمہاری انہی تکلیفوں کے بدلے میں تمہارے لئے جنت تیار
کر رکھی ہے.آخر یا سر تو اس عذاب کی حالت میں جاں بحق ہو گئے اور بوڑھی سمتیہ کی ران میں ظالم
ابو جہل نے اس بے دردی سے نیزہ مارا کہ وہ اس کے جسم کو کاٹتا ہوا ان کی شرمگاہ تک جا نکلا اور اس بے گناہ
خاتون نے اسی جگہ تڑپتے ہوئے جان دے دی.اب صرف عمار باقی رہ گئے.ان کو بھی ان لوگوں نے
انتہائی عذاب اور دکھ میں مبتلا کیا اور ان سے کہا کہ ” جب تک محمدؐ کا کفر نہ کرو گے اسی طرح عذاب دیتے
رہیں گے.چنانچہ آخر عمار نے سخت تنگ آ کر کوئی نازیبا الفاظ منہ سے کہہ دیئے جس پر کفار نے انہیں
چھوڑ دیا.لیکن اس کے بعد عمار فوراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زار زار
رونے لگے.آپ نے پوچھا ” کیوں عمار کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا.”یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا.مجھے ظالموں نے اتنا دکھ دیا کہ میں نے آپ کے متعلق کچھ نا گفتنی الفاظ منہ سے کہہ دیئے.آپ نے
فرمایا: ”تم اپنے دل کا حال کیسا پاتے ہو؟ اُس نے عرض کیا.یا رسول
اللہ میرا دل تو اُسی طرح مومن
ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اُسی طرح سرشار “ آپ نے فرمایا.تو پھر خیر ہے خدا
تمہاری اس لغزش کو معاف کرے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تکالیف مسلمانوں کی ان تکالیف کے مقابلہ پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حالت بھی
مخالفت کے اس طوفان بے تمیزی میں چنداں تسلی بخش نہ تھی.بے شک بنو ہاشم اور بنومطلب کے اس فیصلہ
کے بعد جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے آپ کو اپنے اعزہ واقارب کی عمومی حمایت حاصل تھی اور قریش کی
بین القبائل سیاست میں یہ حمایت خاصہ وزن رکھتی تھی، لیکن اول تو آپ کے چار ابولہب کی بیوفائی اور غداری
نے اس فیصلہ کی طاقت کو ایک حد تک کمزور کر دیا تھا.دوسرے خود قریش بھی یہ دھمکی دے چکے تھے کہ اگر بنو ہاشم
اور بنو مطلب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت و پناہ بننے سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان سب کا
مقابلہ کریں گے اور گوا بھی تک انہوں نے اس دھمکی کو پورے طور پر عملی جامہ نہیں پہنایا تھا، لیکن وہ اس کی
تیاری میں مصروف تھے اور طعن و تشنیع اور نوک جھونک سے گذر کر کبھی کبھی اپنا بچاؤ رکھ کر ملی چھیڑ چھاڑ بھی
کر لیتے تھے ، چنانچہ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک مجلس کر کے اس سوال پر غور کیا کہ اب جو حج کا موسم
آئے گا تو اس موقع پر لازما باہر سے آنے والے حاجیوں میں اسلام کے متعلق چر چا ہو گا اور لوگ آ آ کر ہم سے
Page 176
171
پوچھیں گے کہ یہ نیا نبی کون ہے اور کیا کہتا ہے اس لیے ہمیں باہم مشورہ سے کوئی جواب سوچ رکھنا چاہئے
تا کہ ہمارا آپس کا اختلاف کوئی برا اثر پیدا نہ کرے؛ چنانچہ سب روساء قریش ولید بن مغیرہ کے مکان پر جمع
ہوئے اور ولید نے ان کے سامنے ایک افتتاحی تقریر کر کے ساری بات سمجھائی اور بتایا کہ اب حج کا وقت
آ رہا ہے اور محمد کے اس دعویٰ کی خبر باہر پہنچ چکی ہے اور لازماً حج پر آنے والے لوگ ہمیں اس کے متعلق
پوچھیں گے.پس ہمیں چاہئے کہ ہم باہم مشورہ سے کوئی ایک پختہ جواب سوچ رکھیں تا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم
ایک دوسرے کے خلاف باتیں کہ کر خود اپنے اثر کو مثالیں.اس پر ایک شخص بولا کہ ہمارا جواب صاف ہے
کہ یہ شخص ایک کا ہن ہے اور کاہنوں کی سی باتیں کر کے اس نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے.ولید
نے کہا کہ ہم اسے کا ہن کس طرح کہہ سکتے ہیں جب کہ اس میں کا ہنوں کی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی.نہ
کا ہنوں کا سانتر نم ہے اور نہ کا ہنوں کا سامخصوص انداز بیان.دوسرے نے کہا کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد
مجنون ہے اور اپنے جنون کے جوش میں باتیں کرتا رہتا ہے.ولید نے کہا.ہماری یہ بات کون مانے گا.اور جنون کی وہ کونسی علامتیں ہیں جو ہم محمد میں دکھا سکیں گے.نہ اس میں وہ وحشت ہے اور نہ وہ اضطراب
اور نہ ہی وہ وسوسہ جو ایک مجنون میں لازماً پائے جاتے ہیں.پھر ہمارے جنون کے ادعا کوکون سنے گا.تیسرا
بولا کہ پھر ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے اور اپنے جادُ واثر اشعار سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا
ہے.ولید نے کہا ہم اسے شاعر کہہ کر اس کے کلام میں شعر کے خصائص از قسم رجز اور ہرج اور قریض اور
مقبوض اور مبسوط کہاں سے دکھا ئیں گے.اس پر ایک چوتھا شخص بولا کہ اسے ایک ساحر کے طور پر پیش
کرنا چاہئے.ولید نے کہا پھر ہم اس میں ساحروں کی سی پھونکیں مارنا اور گر ہیں ڈالنا اور گر ہیں کھولنا کس
طرح دکھا ئیں گے.لوگوں نے کہا تو پھر اے عبدشمس تم ہی بتاؤ کہ پھر ہمیں کیا کہنا چاہئے.ولید نے کہا اس
معاملہ میں میں خود حیران ہوں کہ کیا کیا جائے.جو بات بھی سوچتا ہوں وہ محمد پر چسپاں ہوتی نظر نہیں آتی
اور ایسی بات کہنا جس سے لوگوں
کو تسلی نہ ہو خود اپنے آپ
کو نسی کا نشانہ بنانا ہے.اس طرح اس مجلس میں
کچھ عرصہ باتیں ہوتی رہیں.آخر یہ مشورہ قرار پایا کہ اور کوئی بات تو خیال میں آتی نہیں اور جو باتیں پیش
کی گئی ہیں ان میں ساحر والی زیادہ وزن دار ہے.پس یہ فیصلہ ہوا کہ حج کے موقع پر باہر سے آنیوالے
لوگوں کے سامنے محمد کے متعلق سب لوگ یہی کہیں کہ یہ ایک ساحر ہے جو اپنی مخفی سحر کاری سے باپ کو بیٹے
سے ، بھائی کو بھائی سے، خاوند کو بیوی سے جدا کرتا چلا جا رہا ہے؛ چنانچہ جب حج کا موقع آیا تو قریش کے
ا : یہ شعراء عرب کی اصطلاحیں تھیں.
Page 177
۱۶۲
بچہ بچہ کی زبان پر یہی فقرہ تھا کہ محمد تو ایک ساحر ہے جو جس گھر میں داخل ہوتا ہے انشقاق واختلاف کا
بیج بو کر نکلتا ہے اور ان کے اس پروپیگنڈا نے تمام قبائل عرب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام
کے خلاف ایک خطرناک ہیجان پیدا کر دیا.قریش نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ مکہ کے اوباشوں اور خود سر لوگوں کو اکسایا کہ وہ جس طرح بھی ہو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے رہیں؛ چنانچہ اس انگیخت میں آ کر شہر کے آوارہ مزاج لوگ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے سامنے بھی اور پیچھے بھی طرح طرح کی بکواس کرتے رہتے
تھے جس کی غرض سوائے دل دکھانے اور اشتعال پیدا کر کے فساد برپا کرنے کے اور کچھ نہ تھی.جولوگ
آپ کے پڑوس میں رہتے تھے ان کا یہ معمول تھا کہ آپ کے گھر میں پتھر پھینکتے.دروازے پر کانٹے
بچھاتے.گھر کے اندر گندی اور بد بودار چیزیں لا کر ڈال دیتے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان
چیزوں کی وجہ سے عملاً کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ خوش ہو کر بنتے اور قہقہے لگاتے.ایک دفعہ کسی شخص نے ایک
نہایت گندی اور متعفن چیز آپ کے گھر میں پھینک دی.آپ خود اُسے اُٹھا کر باہر لائے اور فرمایا.اے
بنو عبد مناف ! یہ تم اچھا ہمسائیگی کا حق ادا کرتے ہو.مگر جن کانوں تک یہ آواز پہنچتی وہ شرافت کی اپیل
کے لئے بالکل بہرے تھے.انہی دنوں میں قریش نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
بجائے محمد کے مُدمم یعنی بدنام اور مذمت شدہ کہہ کر پکارا جاوے؛ چنانچہ کچھ عرصہ تک مکہ میں اس نام کا
چرچا رہا اور قریش کو اتنی بھی شرم نہ آئی کہ یہ وہی شخص ہے جسے ہم اس کے دعوئی سے پہلے امین کہہ کر
پکارتے رہے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس فعل سے اطلاع ہوئی تو آپ نے مسکراتے
ہوئے فرمایا کہ میرا نام تو محمد ہے اور جو محمد ہو وہ مُذَمَّم کیسے ہوسکتا ہے.دیکھو خدا مجھے ان کی گالیوں سے
کس طرح محفوظ رکھتا ہے.مگر اس زمانہ میں بھی قریش کی ایذاء رسانی صرف زبانی باتوں تک محدود نہ تھی بلکہ وہ بعض اوقات
جوش میں آکر یا موقع نکال کر آپ کو عملی نقصان پہنچانے اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنے سے بھی دریغ
نہ کرتے تھے.چنانچہ غالباً یہ اسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے
عقبہ بن ابی معیط غصہ میں اُٹھا اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس زور کے ساتھ بھینچا کہ آپ کا دم
ل : سیرۃ ابن ہشام
: بخاری باب ماجاء في اسماء الرسول
: تاریخ طبری
Page 178
۱۶۳
رُکنے لگ گیا.حضرت ابو بکر کو علم ہوا تو وہ دوڑے آئے اور آپ کو اس بد بخت کے شر سے بچایا اور قریش
سے مخاطب ہو کر کہا :
اتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ
166
کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میر ارب خدا ہے.“.ایک اور موقع پر آپ نے صحن کعبہ میں توحید کا اعلان کیا تو قریش جوش میں آ کر آپ کے اردگرد
اکٹھے ہو گئے اور ایک ہنگامہ برپا کر دیا.آپ کے ربیب یعنی حضرت خدیجہ کے فرزند حارث بن ابی ہالہ کو
اطلاع ہوئی تو وہ بھاگے آئے اور خطرہ کی صورت پا کر آپ کو قریش کی شرارت سے بچانا چاہا.مگر اس
وقت بعض نوجوانان قریش کے اشتعال کی یہ کیفیت تھی کہ کسی بد باطن نے تلوار چلا کر حارث کو وہیں ڈھیر کر
دیا.اور اس وقت کے شور و شغب میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تلوار چلانے والا کون تھا.ان مصائب پر مسلمانوں کو صبر کی تلقین الغرض یہ وقت اسلام اور اہل اسلام کے لئے سخت
نازک وقت تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی
ذاتی تکلیف کی تو پروا نہیں تھی مگر مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے مصائب کی وجہ سے آپ ضرور
فکرمند تھے ،مگر دوسری طرف آپ اس بات کو بھی خوب جانتے اور سمجھتے تھے کہ قومیں مصائب میں سے گذر
کر ہی بنا کرتی ہیں.اس لئے آپ ایک جہت سے ان مصائب کو مسلمانوں
کی تربیت کا بھی ذریعہ سمجھتے تھے
اور اپنے صحابہ کوصبر ومحل کی تعلیم دیتے اور گذشتہ انبیاء کے متبعین کی تکالیف کا ذکر کر کے ان کو بتاتے تھے کہ
قدیم سے یہی سنت چلی آئی ہے کہ اللہ کے رسولوں اور اُن کے متبعین کو دکھ دیئے جاتے ہیں، لیکن آخر کار
مومنوں کی فتح ہوتی ہے، چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے
پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے خباب بن الارت اور بعض دوسرے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! مسلمانوں کو قریش کے ہاتھ سے اتنی تکالیف پہنچ رہی ہیں آپ ان کے لئے بد دعا
کیوں نہیں کرتے ؟ آپ یہ الفاظ سنتے ہی اُٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا:
دیکھو تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کا گوشت لو ہے کے کانٹوں سے نوچ نوچ کر
ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا مگر وہ اپنے دین سے متزلزل نہیں ہوئے اور وہ لوگ گزرے ہیں جن
کے سروں پر آرے چلا کر ان کو دوٹکڑے کر دیا گیا مگر ان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی.دیکھو خدا
بخاری باب مالقى النبي صلعم ے : اصابہ ذکر حارث
Page 179
۱۶۴
اس کام کو ضرور پورا کرے گا.حتی کہ ایک شتر سوار صنعا (شام) سے لے کے حضر موت تک کا
سفر کرے گا.اور اس کو سوائے خدا کے اور کسی کا ڈر نہ ہوگا.مگر تم تو جلدی کرتے ہو.“
ایک اور موقع پر حضرت عبدالرحمن بن عوف مع چند دوسرے اصحاب کے آپ کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور عرض کیا.یا رسول اللہ ہم مشرک تھے تو ہم معزز تھے.اور کوئی ہماری طرف آنکھ تک نہیں اُٹھا
سکتا تھا لیکن جب سے مسلمان ہوئے ہیں کمزور اور نا تواں ہو گئے ہیں اور ہم کو ذلیل ہو کر کفار کے مظالم
سہنے پڑتے ہیں.پس یا رسول
اللہ ! آپ ہم کو اجازت دیں کہ ہم ان کفار کا مقابلہ کریں.آپ نے فرمایا:
إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ.فَلَا تُقَاتِلُوا
یعنی ”مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو کا حکم ہے.پس میں تم کو لڑنے کی اجازت نہیں
دے سکتا.“
صحابہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کے سامنے سرتسلیم خم تھا.انہوں نے صبر اور برداشت
کا وہ نمونہ دکھایا کہ تاریخ اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے.بخاری باب علامات نبوت و باب مالقى النبى و اصحابه من المشركين
ے نسائی بحوالہ تلخیص الصحاح جلد ا صفحه ۱۵۲
Page 180
ܬܪܙ
ایام
کش مکش
ہجرت حبشہ جب مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی او قریش اپنی ایذاء رسانی میں ترقی کرتے گئے تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں
اور فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ عادل اور انصاف پسند ہے.اس کی حکومت میں
کسی پر ظلم نہیں ہوتا.‘ے حبشہ کا
ملک جو انگریزی میں ایتھوپی یا آبی سینیا کہلاتا ہے، بر اعظم افریقہ کے شمال مشرق میں واقع ہے اور جائے
وقوع کے لحاظ سے جنوبی عرب کے بالکل مقابل پر ہے اور درمیان میں بحیرہ احمر کے سوا کوئی اور ملک
حائل نہیں.اس زمانہ میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم تھی اور وہاں
کا بادشاہ نجاشی کہلاتا تھا.بلکہ ابتک بھی وہاں کا حکمران اسی نام سے پکارا جاتا ہے.حبشہ کے ساتھ عرب کے تجارتی تعلقات تھے یہ
اور ان ایام میں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں حبشہ کا دارالسلطنت اکسوم (Axsum) تھا جو موجودہ شہر عدوا
(Adowa) کے قریب واقع ہے اور اب تک ایک مقدس شہر کی صورت میں آباد چلا آتا ہے.اکسوم ان
دنوں میں ایک بڑی طاقتور حکومت کا مرکز تھا.اور اس وقت کے نجاشی کا ذاتی نام اصحمہ تھا جو ایک عادل
بیدار مغز اور مضبوط بادشاہ تھا.بہر حال جب مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جن جن سے ممکن ہو حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں.چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر ماہ رجب ۵ نبوی میں گیارہ مرد اور چار عورتوں نے حبشہ کی طرف
ہجرت کی.اُن میں سے زیادہ معروف کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ رقیہ بنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، ابو حذیفہ بن عقبہ، عثمان بن مظعون ،
مصعب بن عمیر، ابوسلمہ بن عبدالاسد اور ان کی زوجہ اُم سلمہ نے یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان ابتدائی
مہاجرین میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو قریش کے طاقتور قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور کمز ور لوگ کم نظر
ل : ابن ہشام وطبری
: طبری
: چیمبرس انسائیکلو پیڈیا
: بخاری و زرقانی
ه : ابن سعد
: ابن ہشام
Page 181
۱۶۶
آتے ہیں جس سے دو باتوں کا پتا چلتا ہے.اول یہ کہ طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی قریش
کے مظالم سے محفوظ نہ تھے.دوسرے یہ کہ کمز ور لوگ مثلاً غلام وغیرہ اس وقت ایسی کمزوری اور بے بسی کی
حالت میں تھے کہ ہجرت کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے.جب یہ مہاجرین جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے شعیہ پہنچے جو اُس زمانہ میں عرب کا ایک بندرگاہ تھا
تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ ان کو ایک تجارتی جہاز مل گیا جو حبشہ کی طرف روانہ ہونے کو بالکل تیار تھا؛
چنانچہ یہ سب امن سے اس میں سوار ہو گئے اور جہاز روانہ ہو گیا.قریش مکہ کو ان کی ہجرت کا علم ہوا تو
سخت برہم ہوئے کہ یہ شکار مفت میں ہاتھ سے نکل گیا.چنانچہ انہوں نے ان مہاجرین کا پیچھا کیا مگر جب
ان کے آدمی ساحل پر پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا، اس لئے خائب و خاسر واپس لوٹے.حبشہ میں پہنچ کر
مسلمانوں کو نہایت امن کی زندگی نصیب ہوئی اور خدا خدا کر کے قریش کے مظالم سے چھٹکار املا.بعض
قریش کے اسلام کی جھوٹی افواہ اور بعض مہاجرین حبشہ کی واپسی مین جیسا کہ اس
مؤرخین نے بیان کیا
ہے ابھی ان مہاجرین کو حبشہ میں گئے زیادہ عرصہ نہ گذرا تھا کہ ایک اُڑتی ہوئی افواہ ان تک پہنچی کہ تمام قریش
مسلمان ہو گئے ہیں مکہ میں اب بالکل امن و امان ہے.اس خبر کا یہ نتیجہ ہوا کہ اکثر مہاجرین بلا سوچے سمجھے
وا پس آگئے.جب یہ لوگ مکہ کے پاس پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی.اب ان کے لئے بڑی مصیبت کا
سامنا تھا.بالآ خر بعض تو راستہ میں سے ہی واپس لوٹ گئے اور بعض چھپ چھپ کر یا کسی ذی اثر اور طاقتور
شخص کی حمایت میں ہو کر مکہ میں آگئے.یہ شوال ۵ نبوی کا واقعہ ہے کے یعنی آغاز ہجرت اور مہاجرین کی
واپسی کے درمیان صرف ڈھائی تین ماہ کا فاصلہ تھا.کیونکہ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں حبشہ کی ہجرت
رجب کے مہینہ میں ہوئی تھی اور مہاجرین کی مزعومہ واپسی کی تاریخ شوال بیان کی گئی ہے.گو حقیقہ یہ افواہ بالکل جھوٹی اور بے بنیاد تھی جو مہاجرین حبشہ کو واپس لانے اور ان کو تکلیف میں
ڈالنے کی غرض سے قریش نے مشہور کر دی ہوگی بلکہ زیادہ غور سے دیکھا جاوے تو اس افواہ اور مہاجرین
کی واپسی کا قصہ ہی بے بنیاد نظر آتا ہے لیکن اگر اسے صحیح سمجھا جاوے تو ممکن ہے کہ اس کی تہ میں وہ واقعہ ہو
جو بعض احادیث میں بیان ہوا ہے اور وہ جیسا کہ بخاری میں آتا ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے صحن کعبہ میں سورۃ نجم کی آیات تلاوت فرمائیں.اس وقت وہاں کئی ایک رؤساء کفار بھی
له : ابن سعد وزرقانی
: زرقانی
: ابن سعد
Page 182
۱۶۷
موجود تھے اور بعض مسلمان بھی تھے.جب آپ نے سورۃ ختم کی تو آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ ہی
تمام مسلمان اور کا فر بھی سجدہ میں گر گئے.کفار کے سجدہ کی وجہ حدیث میں بیان نہیں ہوئی لیکن معلوم
ہوتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پر اثر آواز میں آیات الہی کی تلاوت فرمائی اور وہ
آیات بھی ایسی تھیں جن میں خصوصیت کے ساتھ خدا کی واحدانیت اور اس کی قدرت و جبروت کا نہایت
فصیح و بلیغ رنگ میں نقشہ کھینچا گیا تھا اور اس کے احسانات یاد دلائے گئے تھے اور پھر ایک نہایت پر رعب و
پر جلال کلام میں قریش کو ڈرایا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ان کا وہی حال ہوگا جو اُن
سے پہلے اُن قوموں کا ہوا جنہوں نے خدا کے رسولوں کی تکذیب کی اور پھر آخر میں ان آیات میں حکم دیا
گیا تھا کہ آؤ اور اللہ کے سامنے سجدہ میں گر جاؤ اور ان آیات کی تلاوت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور سب مسلمان یکلخت سجدہ میں گر گئے تو اس کلام اور اس نظارہ کا ایسا ساحرانہ اثر قریش پر ہوا کہ وہ بھی
بے اختیار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ سجدہ میں گر گئے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ایسے موقعوں پر
ایسے حالات کے ماتحت جو اوپر بیان ہوئے ہیں بسا اوقات انسان کا قلب مرعوب ہو جاتا ہے اور وہ
بے اختیار ہوکر ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو دراصل اس کے اصول و مذہب کے خلاف ہوتی ہے؛ چنانچہ ہم
نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک سخت اور نا گہانی آفت کے وقت ایک دہر یہ بھی اللہ اللہ یا رام رام“
پکار اٹھتا ہے اور قریش تو دہر یہ نہ تھے بلکہ بہر حال خدا کی ہستی کے قائل تھے.پس جب اس پر رعب و پر جلال
کلام کی تلاوت کے بعد مسلمانوں کی جماعت یکلخت سجدہ میں گر گئی تو اس کا ایسا ساحرانہ اثر ہوا کہ ان کے
ساتھ قریش بھی بے اختیار ہو کر سجدہ میں گر گئے.لیکن ایسا اثر عموماً وقتی ہوتا ہے اور انسان پھر جلد ہی اپنی
اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے؛ چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا اور سجدہ سے اُٹھ کر قریش پھر وہی بت پرست
کے بت پرست تھے.بہر حال یہ ایک واقعہ ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے.پس اگر مہاجرین حبشہ کی واپسی کی خبر
درست ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد قریش نے جو مہاجرین حبشہ کے واپس لانے کے لیے
بیتاب ہو رہے تھے اپنے اس فعل کو آڑ بنا کر خود ہی یہ افواہ مشہور کر دی ہوگی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے
ہیں اور یہ کہ اب مکہ میں مسلمانوں کے لئے بالکل امن ہے اور جب یہ افواہ مہاجرین حبشہ تک پہنچی تو وہ
طبعاً اُسے سن کر بہت خوش ہوئے اور سنتے ہی خوشی کے جوش میں واپس آگئے لیکن جب وہ مکہ کے پاس
ل : بخاری تفسیر سورۃ نجم
۲ : دیکھئے سورۃ نجم : ۶۳
Page 183
۱۶۸
پہنچے تو حقیقت امر سے آگاہی ہوئی جس پر بعض تو چھپ چھپ کر اور بعض کسی طاقتور اور صاحب اثر رئیس
قریش کی حفاظت میں ہو کر مکہ میں آگئے اور بعض واپس چلے گئے.پس اگر قریش کے مسلمان ہو جانے کی
افواہ میں کوئی حقیقت تھی تو وہ صرف اسی قدر تھی جو سورۃ نجم کی تلاوت پر سجدہ کرنے والے واقعہ میں بیان
ہوئی ہے.واللہ اعلم.بہر حال اگر مهاجرین حبشہ واپس آئے بھی تھے تو اُن میں سے اکثر پھر واپس چلے گئے اور چونکہ
قریش دن بدن اپنی ایذاء رسانی میں ترقی کرتے جاتے تھے اور ان کے مظالم روز بروز بڑھ رہے تھے.اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دوسرے مسلمانوں نے بھی خفیہ خفیہ ہجرت کی تیاری شروع
کر دی اور موقع پا کر آہستہ آہستہ نکلتے گئے.یہ ہجرت کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ بالآخران مہاجرین حبشہ
کی تعداد ایک سو ایک تک پہنچ گئی جن میں اٹھارہ عورتیں بھی تھیں.اور مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس بہت ہی تھوڑے مسلمان رہ گئے.اس ہجرت کو بعض مؤرخین ہجرت حبشہ ثانیہ کے نام سے
موسوم کرتے ہیں.ایک جھوٹا واقعہ ہجرت حبشہ کے تعلق میں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ کفار قریش کے سجدہ کرنے
اور مہاجرین حبشہ کے واپس چلے آنے کے متعلق بعض مؤرخین ایک عجیب قصہ نقل
کرتے ہیں جو یہ ہے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا از حد شوق رہتا تھا کہ اللہ کی طرف
سے کوئی ایسی بات نازل ہو جو قریش کو اسلام کی طرف کھینچنے والی اور ان کی منافرت کو دور کرنے والی ہو.الہذا جب آپ سورۃ نجم کی آیات تلاوت فرماتے ہوئے ان آیات پر پہنچے کہ :
أَفَرَءَ يْتُمُ اللَّهَ وَالْعُزَّى وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرُى
یعنی کیا تم نے مشرکین کے بتوں لات اور عزی اور منات کی طرف دیکھا ہے؟“
تو شیطان نے آپ کے اس شوق سے فائدہ اُٹھایا اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیئے کہ :
تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَا عَتَهُنَّ لَتُرْتَجِى
د یعنی لات اور عزمی اور منات بڑے جلیل القدر بت ہیں اور ان کی شفاعت کی اُمید
رکھنی چاہئے.“
جب قریش نے یہ الفاظ سنے تو وہ خاموش ہو گئے کہ ان کے بتوں کی عظمت اور قوت کو مان لیا گیا
ل : زرقانی
ہے : سورة النجم: ۲۰
۲۱ ، ۲۰:
Page 184
۱۶۹
ہے.لہذا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سورۃ نجم ختم کرنے پر سجدہ کیا تو قریش نے
بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور اس طرح گویا صلح صفائی ہوگئی.لیکن اس کے بعد جلد ہی جبرائیل آپ کے
پاس آئے اور آپ کو اس غلطی سے آگاہ کیا اور شیطان کی القاء کردہ آیت کی جگہ وہ الہی کلام آپ پر وحی
کیا جو اب قرآن شریف میں موجود ہے اور اس طرح قریش پھر ناراض ہو گئے لیکن چونکہ قریش کے
ساتھ صلح صفائی ہو جانے کی خبر شائع ہو چکی تھی اس لئے پیشتر اس کے کہ اس کی تردید ہوتی وہ حبشہ بھی
پہنچ گئی اور اس طرح بعض مہاجرین واپس آگئے.یہ وہ قصہ ہے جو اس موقع پر بعض مؤرخین لکھتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ یہ قصہ سراسر جھوٹ ہے
اور ہر معقول رنگ میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہے؛ چنانچہ کبار محدثین اور ائمہ حدیث مثلاً علامہ عینی.قاضی عیاض اور علامہ نووی نے کھول کھول کر اور دلائل دے دے کر اس کو غلط اور موضوع ثابت کیا ہے.چنانچہ علامہ عینی اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
لاصِحَةَ لَهُ نَقَلًا وَّلَا عَقَلَا
یعنی دنقل اور عقل دونوں سے یہ قصہ غلط ثابت ہوتا ہے.“
اور قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ :
لَمْ يَخْرُجُهُ أَهْلُ الصَّحَةِ وَلَا رَوَاهُ ثِقَةٌ بِسَنَدٍ سَلِيْمٍ مَعَ ضُعْفِ نَقْلَتِهِ
وَاضْطِرَابِ رِوَايَاتِهِ وَانْقِطَاعِ اَسَانِيدِهِ وَاَكْثَرُ الطُّرُقِ فِيهَا ضَعِيْفَةٌ وَاهِيَةٌ لَمْ
يَسُنِدَ هَا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا رَفَعَهَا إِلَى صَاحِبٍ
یعنی محتاط اور ثقہ لوگوں نے اس کی روایت نہیں کی، کیونکہ اس قصہ میں روایت کا
اضطراب اور سند کی کمزوری بہت پائی جاتی ہے.اور اس کے طریقے بہت کمزور اور بودے
ہیں.اور کسی راوی نے اس کی سند کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آپ کے کسی صحابی تک
نہیں پہنچایا.“
اور علامہ نووی لکھتے ہیں :
لا يَصِحُ فِيْهِ شَيْءٌ لَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ
ا : عینی شرح بخاری
ے : شفا قاضی عیاض بحوالہ زرقانی
: نووی شرح مسلم
Page 185
۱۷۰
یعنی اس قصہ میں کوئی بات بھی درست نہیں نہ نقل کے طریق پر اور نہ عقل کے طریق پر.دوسری طرف اکثر ائمۃ الحدیث نے اس قصہ کا ذکر تک نہیں کیا.مثلاً صحاح ستہ میں اس کی طرف
اشارہ تک نہیں ؛ حالانکہ صحاح ستہ میں سورۃ نجم کی تلاوت اور قریش کے سجدہ کا ذکر موجود ہے جس سے
صاف ظاہر ہے کہ ان محدثین کے سامنے یہ روایت آئی.لیکن انہوں نے اسے غلط اور نا قابلِ اعتبار
سمجھ کر رد کر دیا.اسی طرح کبار مفسرین مثلاً امام رازی نے اس قصہ کو لغوا اور جھوٹا قرار دیا ہے.اور صوفیاء میں سے
ابن عربی جیسے باریک بین انسان نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ: "لَا أَصْلَ لَهَا.یعنی اس قصہ میں کچھ
بھی حقیقت نہیں.ویسے بھی اگر صرف سورۃ نجم کی آیات پر ہی جو شروع سے لے کر آخر تک شرک کے
خلاف بھری پڑی ہیں نظر ڈالی جاوے تو اُسی سے اس کا بطلان ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ہرگز خیال نہیں کیا
جاسکتا کہ اس قسم کے موحدانہ کلام میں جس میں توحید باری تعالیٰ پر اس قدر زور دیا گیا ہے ایک صریح طور
پر مشرکانہ فقرہ داخل کیا جا سکتا تھا اور ایک ہی وقت میں ایک ہی زبان پر دو انتہائی طور پر متضاد باتیں جاری
ہو سکتی تھیں.پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے لحاظ سے بھی عقل انسانی اس قصہ کو دور
سے دھکے دیتی ہے.بھلا جس شخص نے اپنی بعثت سے پہلے بھی ساری عمر بت پرستی نہ کی ہو حالانکہ اس کی
ساری قوم بت پرست ہو تو کیا عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ اس وقت جب کہ اس کے پاس اللہ
تعالیٰ کا صریح حکم آگیا ہو کہ بت پرستی کے خلاف آواز اُٹھا اور صرف خدائے واحد کی پرستش کا لوگوں کو حکم
دے اور اس کے مذہب کا بنیادی پتھر ہی تو حید باری تعالیٰ ہو جس کی وجہ سے وہ دن رات لوگوں کے ساتھ
جھگڑتا ہو تو کیا اس وقت وہ قریش کو خوش کرنے کے لئے بت پرستی کی طرف جھک جائے گا؟ آخر عقل بھی
کوئی چیز ہے؟ ذرا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالو.کیا کبھی آپ نے کفار کو خوش کرنے کی
غرض سے اپنے مذہب کے کسی اصول کو چھوڑا ؟ کیا کبھی آپ نے کفار کو اپنے ساتھ ملانے کی غرض سے
مداہنت اختیار کی ؟ قرآن تو صریح کہتا ہے:
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ "
یعنی کفار کو ہمیشہ یہ حسرت ہی رہی کہ تو مداہنت کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملا وے تو وہ
بھی مداہنت اختیار کر لیں اور اس طرح ظاہری صورت میل ملاپ کی ہو جاوے.“
ل : تفسیر کبیر باب سورۃ نجم ۶۳۱ : زرقانی
سے : سورة القلم : ١٠
Page 186
11
کیا ایسے شخص کی نسبت یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُس نے کبھی قریش کی خاطر تو حید کو چھوڑ کر شرک اختیار کیا ہوگا ؟
البتہ ایک تو جبیہ اس قصہ کی ممکن ہے اور جیسا کہ علامہ قسطلانی اور زرقانی نے لکھا ہے اور بہت سے محققین
نے اس کی تائید کی ہے.ممکن ہے کہ یہ توجیہ درست ہو اور وہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بخاری کی روایت کے مطابق صحن کعبہ میں سورۃ نجم کی آیات تلاوت فرمائی ہوں تو ممکن ہے کہ
شیاطین قریش میں سے کسی نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَیٰ کا فقرہ ملا دیا ہو
جس کی وجہ سے اس وقت بعض لوگوں میں اشتباہ واقع ہو گیا ہو کہ شاید یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہے ہیں کیونکہ یہ ثابت ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کے وقت قریش کی یہ عام عادت تھی کہ وہ اس
کے اثر کو مٹانے کے لئے شور کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ان کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ :
لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ
یعنی قریش کہا کرتے تھے کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاوے تو اُس میں شور
کر کے گڑ بڑ پیدا کر دیا کرو.شاید اس طرح تم غالب آ سکو.“
اس توجیہ کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ کعبہ کا
طواف کرتے ہوئے یہی فقرہ تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلیٰ والا پڑھا کرتے تھے تے پس تعجب نہیں کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی آیات تلاوت فرمائی ہوں تو اُن میں سے کسی نے حسب عادت
یہاں بھی اس فقرہ کو داخل کر دیا ہو.اور اس طرح بعض لوگوں کو عارضی طور پر یہ اشتباہ واقع ہو گیا ہو کہ شاید
یہ الفاظ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہیں.اس توجیہہ کی تائید ابن عربی.قاضی عیاض،
ابن جریر، امام رازکی اور حافظ ابن حجر نے بھی کی ہے.لیکن ایک اور بات ہے جو اس افواہ اور مہاجرین کی
واپسی کے قصہ کو سرے سے ہی مشتبہ کر دیتی ہے اور وہ یہ کہ تاریخ میں ہجرت حبشہ کے آغاز کی تاریخ
رجب پانچ نبوی اور سجدہ کی تاریخ رمضان پانچ نبوی بیان ہوئی ہے اور پھر تاریخ میں ہی یہ بات بھی بیان
ہوئی ہے کہ اس افواہ کے نتیجہ میں مہاجرین حبشہ کی واپسی شوال ۵ نبوی میں ہوئی تھی ہے گویا آغا ز ہجرت اور
واپسی مہاجرین کے زمانوں میں صرف دو سے لے کر تین ماہ کا فاصلہ تھا اور اگر سجدہ کی تاریخ سے زمانہ کا
شمار کریں تو یہ عرصہ صرف ایک ہی ماہ کا بنتا ہے.اب اُس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے یہ قطعی طور پر ناممکن
: معجم البلدان جلد ۵ زیر بحث عزمی
لا : سورة حم سجدہ: ۲۷
: زرقانی جلد ا باب دخول الشعب ابن سعد حالات واپسی مهاجرین حبشه
Page 187
۱۷۲
ہے کہ مکہ اور حبشہ کے درمیان اس قلیل عرصہ میں تین سفر مکمل ہو سکے ہوں یعنی سب سے پہلے مسلمان مکہ
سے حبشہ پہنچے.اس کے بعد کوئی شخص قریش کے اسلام کی خبر لے کر ملکہ سے حبشہ گیا اور پھر مسلمان حبشہ سے
روانہ ہو کر مکہ میں واپس آئے.ان تین سفروں کی تکمیل قطع نظر اس عرصہ کے جو زائد امور میں صرف ہو
جاتا ہے اس قلیل عرصہ میں قطعا ناممکن تھی.اور اس سے بھی زیادہ یہ بات ناممکن تھی کہ سجدہ کے زمانہ سے
لے کر مہاجرین حبشہ کی مذعومہ واپسی تک دوسفر مکمل ہو سکے ہوں کیونکہ اس زمانہ میں مکہ سے حبشہ جانے
کے لئے پہلے جنوب میں آنا پڑتا تھا اور پھر وہاں سے کشتی لے کر جو ہر وقت موجود نہیں ملتی تھی بحر احمر کو عبور
کر کے افریقہ کے ساحل تک جانا ہوتا تھا اور پھر ساحل سے لے کر حبشہ کے دارالسلطنت اکسوم تک جو
ساحل سے کافی فاصلہ پر ہے پہنچنا پڑتا تھا.اور اس زمانہ کے آہستہ سفروں کے لحاظ سے اس قسم کا ایک سفر
بھی ڈیڑھ دو ماہ سے کم عرصہ میں ہر گز مکمل نہیں ہو سکتا تھا.اس جہت سے گویا یہ قصہ سرے سے ہی غلط اور
بے بنیاد قرار پاتا ہے لیکن اگر بالفرض اس میں کوئی حقیقت تھی بھی تو وہ یقینا اس سے زیادہ نہیں تھی جو اوپر
بیان کی گئی ہے.واللہ اعلم
نجاشی کے دربار میں قریش کا نا کام وفد بہر حال قریش نے جب مسلمانوں کو اس طرح اپنے
ہاتھوں سے صحیح سلامت نکلے جاتے دیکھا اور حبشہ
میں ان کو امن و امان کی زندگی بسر کرتے پایا تو ان کے غضب کی آگ اور بھڑک اٹھی اور بالآ خر ا نہوں نے
اپنے دو ممتاز ممبر یعنی ایک عمر و بن العاص اور دوسرے عبد اللہ بن ربیعہ کوحبشہ کی طرف روانہ کرنے کی تجویز
کی اور اس وفد کے ساتھ نہ صرف نجاشی کے واسطے گراں قیمت تحفے تیار کئے بلکہ اس کے تمام درباریوں
کے واسطے بھی تحائف تیار کئے گئے جو زیادہ تر چمڑے کے سامان کے تھے جس کے لئے ان دنوں میں عرب
خاص شہرت
رکھتا تھا اور اس طرح بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ یہ وفد روانہ ہوا.اس وفد کی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں
کو حبشہ سے واپس لا کر پھر ان کو اپنے مظالم کا تختہ مشق بنا ئیں؛ چنانچہ حبشہ میں پہنچ کر عمر و بن العاص اور ان
کے ساتھی نے پہلے نجاشی کے درباریوں کے ساتھ ملاقات کی اور اُن کے سامنے تحائف پیش کئے اور پھر
ان کے ذریعہ سے نجاشی کے دربار تک رسائی حاصل کی اور تحفے تحائف پیش کرنے کے بعد نجاشی سے ان
الفاظ میں درخواست کی کہ : ”اے بادشاہ سلامت ہمارے چند بیوقوف لوگوں نے اپنا آبائی مذہب ترک
کر دیا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے جو آپ کے دین کے بھی مخالف ہے اور ان لوگوں نے ملک میں فساد
ڈال دیا ہے اور اب ان میں سے بعض لوگ وہاں سے بھاگ کر یہاں آگئے ہیں.پس ہماری یہ درخواست
Page 188
۱۷۳
ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھجوا دیں.درباریوں نے ان کی تائید کی لیکن نجاشی نے جو ایک
بیدار مغز حکمران تھا یکطرفہ فیصلہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ میری پناہ میں آئے ہیں.پس جب
تک میں خود ان کا اپنا بیان نہ سن لوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا.چنانچہ مسلمان مہاجرین دربار میں بلائے گئے
اور اُن سے مخاطب ہو کر نجاشی نے پوچھا کہ ”یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا دین ہے جو تم نے نکالا ہے؟“
حضرت جعفر بن ابی طالب نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا کہ ”اے بادشاہ! ہم جاہل لوگ تھے.بت پرستی کرتے تھے.مُردار کھاتے تھے.بدکاریوں میں مبتلا تھے.قطع رحمی کرتے تھے.ہمسایوں سے
بد معاملگی کرتے تھے اور ہم میں سے مضبوط کمزور کا حق دبا لیتا تھا.اس حالت میں اللہ نے ہم میں اپنا ایک
رسول بھیجا جس کی نجابت اور صدق اور امانت کو ہم سب جانتے تھے.اُس نے ہم کو تو حید سکھائی اور بت
پرستی سے روکا اور راست گفتاری اور امانت اور صلہ رحمی کا حکم دیا اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی
تعلیم دی اور بدکاری اور جھوٹ اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا اور خونریزی سے روکا اور ہم کو عبادتِ
الہی کا حکم دیا.ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی اتباع کی لیکن اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہوگئی
اور اُس نے ہم کو دکھوں اور مصیبتوں میں ڈالا اور ہم کو طرح طرح کے عذاب دیئے اور ہم کو اس دین سے
جبر اروکنا چاہا.حتی کہ ہم تنگ آ کر اپنے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی.پس اے
بادشاہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہم پر ظلم نہ ہو گا.نجاشی اس تقریر سے بہت متاثر ہوا اور
حضرت جعفر سے کہنے لگا کہ جو کلام تم پر اُتر ا ہے وہ مجھے سناؤ اس پر حضرت جعفر نے بڑی خوش الحانی کے
ساتھ سورۃ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں.یہ آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری
ہو گئے اور اس نے رقت کے لہجہ میں کہا: خدا کی قسم یہ کلام اور ہمارے مسیح کا کلام ایک ہی منبع نور کی کرنیں
معلوم ہوتی ہیں.“ یہ کہہ کر نجاشی نے قریش کے وفد سے کہا.” تم واپس چلے جاؤ.میں ان لوگوں کو
تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا.‘ اور نجاشی نے ان کے تھنے بھی واپس کر دئیے.لیکن قریش کے خونی سفیر اس طرح آسانی کے ساتھ خاموش نہیں کئے جاسکتے تھے.دوسرے دن عمر و
بن العاص نے دربار میں پھر رسائی حاصل کی اور نجاشی سے عرض کیا کہ حضور آپ
کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ
لوگ مسیح کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا.مسلمان فکرمند ہوئے کہ چونکہ ہم مسیح
کے ابن اللہ ہونے کے منکر ہیں اس لئے کہیں عمرو بن العاص کی یہ چال چل نہ جاوے.مگر یہ لوگ تلوار کے
سایہ کے نیچے بھی حق بات کہنے سے رکنے والے نہ تھے ، چنانچہ جب نجاشی نے پوچھا کہ ” تم مسیح کے متعلق کیا
Page 189
۱۷۴
اعتقاد ر کھتے ہو؟“ تو جعفر نے صاف عرض کیا کہ اے بادشاہ ! ہمارے اعتقاد کی رُو سے مسیح اللہ کا ایک
بندہ ہے خدا نہیں ہے مگر وہ اس کا ایک بہت مقرب رسول ہے اور اس کے اُس کلام سے عالم ہستی میں آیا
ہے جو اُس نے مریم پر ڈالا.نجاشی نے فرش پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا.”واللہ جو تم نے بیان کیا ہے
میں اس سے میسیج کو اس تنکے کے برابر بھی بڑا نہیں سمجھتا.نجاشی کے اس کلام پر دربار کے پادری سخت برہم
ہوئے مگر نجاشی نے ان کی کچھ پروانہ کی اور قریش کا وفد بے نیل مرام واپس آ گیا.اس کے بعد مہاجرین حبشہ ایک عرصہ تک بڑے امن کے ساتھ حبشہ میں رہے لیکن اُن میں سے
اکثر تو ہجرت میثرب کے قریب مکہ میں واپس آگئے اور بعض حبشہ میں ہی مقیم رہے حتی کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور جنگ بدر اور اُحد اور احزاب تمام ہو چکیں تب یہ لوگ عرب میں
واپس آئے.یہ وہ زمانہ تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپس آ رہے تھے.ابتداء میں جبکہ ابھی اکثر مہاجرین حبشہ میں ہی تھے نجاشی کو اپنے ایک حریف سے جنگ پیش آ گئی.اس پر صحابہ نے باہم مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو ہمیں بھی نجاشی کی امداد کرنی
چاہئے چنانچہ انہوں نے زبیر ابن العوام کو دریائے نیل کے پارمیدانِ جنگ میں بھیجا کہ حالات سے
اطلاع دیں اور پیچھے صحابہ خدا سے دعائیں کرتے رہے کہ نجاشی کو فتح ہو.چنانچہ چند دن کے بعد حضرت
زبیر نے واپس آکر اطلاع دی کہ نجاشی نے خدا کے فضل سے فتح پائی ہے.یہ
حضرت ابوبکر کا ہجرت کے ارادے سے نکلنا حدیث میں حضرت عائشہ سے روایت آتی
ہے کہ جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت
کر گئے تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر بھی ہجرت کے ارادہ سے مکہ سے نکلے مگر جب جنوب کی طرف جاتے
ہوئے برک العماد میں پہنچے تو وہاں اتفاقاً قبیلہ قارہ کے رئیس ابن الدغنہ سے ملاقات ہوگئی.ابن الدغنہ
نے اس سفر کا سبب پوچھا تو حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ ” میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے میں
نے اب ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین میں کہیں نکل جاؤں اور آزاد ہو کر اپنے رب کی عبادت کروں.“
ابن الدغنہ نے کہا.” تمہارے جیسے شخص کو تو نہ خود مکہ سے نکلنا چاہئے اور نہ لوگوں کو چاہئے کہ اسے نکالیں
آؤ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں.واپس لوٹ چلو اور مکہ میں ہی اپنے رب کی عبادت کرو.“
چنانچہ ابو بکر ان کے کہنے پر واپس چلے آئے.مکہ پہنچ کر ابن الدغنہ نے رؤساء قریش کو ملامت کی اور کہا کہ :
لے : ان جملہ حالات کے لیے دیکھو ابن ہشام وزرقانی وطبری وا بن سعد و بخاری
Page 190
۱۷۵
کیا تم ایسی ایسی نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو؟ اس کے بعد حضرت ابو بکڑ نے اپنے گھر کے صحن میں
ایک چھوٹی سی مسجد بنالی جس میں وہ نماز اور قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اور چونکہ وہ نہایت رقیق القلب
تھے.اس لیے جب وہ قرآن شریف پڑھتے تو بسا اوقات ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے.قریش کی عورتیں
اور بچے جو نسبتاً سادہ طبع اور تعصبات مذہبی سے آزاد تھے یہ نظارہ دیکھتے تو ان کے قلوب پر اس کا ایک خاص
اثر ہوتا اور چونکہ ویسے بھی حضرت ابو بکر قریش میں بہت معزز تھے اس لیے ان کی یہ والہانہ عبادت لوگوں
کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرتی تھی.اس پر قریش نے ابن الدغنہ کے پاس شکایت کی کہ ابو بکر
اونچی آواز سے قرآن پڑھتا ہے اور اس سے ہماری عورتیں اور بچے اور کمز ور لوگ فتنہ میں پڑتے ہیں.لہذا تم اسے روک دو.اس نے حضرت ابو بکر کو روکنا چاہا.مگر اُنہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ: ”میں یہ
کام ہرگز نہیں چھوڑ سکتا.ہاں اگر تمہیں کوئی ڈر ہے تو میں تمہاری پناہ سے نکلتا ہوں مجھے اپنے مولیٰ کی پناہ
بس ہے.اس کے بعد قریش نے حضرت ابو بکر کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں مگر وہ ایک مضبوط چٹان
اسلام حمزه
کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہے.ہجرت حبشہ کے متعلق سلسلہ واقعات کو ایک جگہ بیان کرنے کی وجہ سے ہم نے بعض درمیانی
واقعات کا ذکر چھوڑ دیا تھا.وہ اب بیان کرتے ہیں.اب تک مسلمانوں کی ظاہری حالت
نہایت کمزور تھی کیونکہ مسلمان ہونے والوں میں سے سوائے حضرت ابو بکر کے ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو
قریش میں کوئی اثر رکھتا ہو یا کم از کم جس سے قریش کچھ دیتے ہوں مگر اب خدا کے فضل سے دو ایسے شخص
اسلام میں داخل ہوئے جو اپنی وجاہت اور رعب کی وجہ سے اسلام کی ظاہری شان کو ایک حد تک مضبوط
کرنے والے ثابت ہوئے.ہماری مراد حضرت حمزہ بن عبدالمطلب اور حضرت عمر بن الخطاب سے ہے
جو دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے 4 نبوی میں مسلمان ہوئے.حمزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاتھے اور اُن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت
تھی لیکن ابھی تک مشرک تھے.ان کا یہ معمول تھا کہ ہر روز صبح سویرے تیر کمان لے کر باہر نکل جاتے تھے
اور سارا دن شکار کھیلتے رہتے تھے.شام کو واپس آکر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور پھر قریش کی ان
مجلسوں میں دورہ لگاتے جو وہ صحن کعبہ میں دو دو چار چار کی ٹولیوں میں جما کر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں
سے فارغ ہونے کے بعد گھر جاتے تھے.ایک دن حمزہ اسی طرح شکار سے واپس آئے تو ایک خادمہ نے
ل : بخاری ابواب الہجرت
Page 191
اُن سے کہا.” کیا آپ نے سنا کہ ابھی ابھی ابو الحکم (یعنی ابو جہل ) آپ کے بھتیجے کوسخت بُرا بھلا کہتا گیا
ہے اور بہت گندی گندی گالیاں دی ہیں.مگر محمد نے سامنے سے کچھ جواب نہیں دیا.یہ سن کر حمزہ کی
آنکھوں میں خون اتر آیا اور خاندانی غیرت جوش زن ہوئی.فوراً کعبہ کی طرف گئے اور پہلے طواف کیا.طواف کرنے کے بعد اس مجلس کی طرف بڑھے جس میں ابو جہل بیٹھا تھا اور جاتے ہی بڑے زور کے ساتھ
ابو جہل کے سر پر اپنی کمان ماری اور کہا.”میں سنتا ہوں کہ تو نے محمد کو گالیاں دی ہیں.سن میں بھی محمد کے
دین پر ہوں اور میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے.پس اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو میرے سامنے
بول.ابو جہل کے ساتھی ابو جہل کی حمایت میں اُٹھے اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی مگر ابو جہل حمزہ کی دلیری
اور جرات کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور اُس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ حمزہ حق بجانب ہے
واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی اور اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا.حمزہ جوش میں یہ الفاظ تو کہ بیٹھے تھے کہ "میں بھی محمد کے دین پر ہوں.لیکن جب گھر آئے اور
غصہ کم ہوا تو کچھ گھبرائے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیئے آخر دل نے یہی فیصلہ کیا کہ اب شرک
چھوڑ دینا ہی بہتر ہے.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو
گئے نے یہ بعثت نبوی کے چھٹے سال کا واقعہ ہے جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دارارقم میں ہی مقیم
تھے کہ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے کی خوشی میں یا ویسے ہی اپنے اخلاص کے جوش میں مگر بہر حال اُسی
دن جس دن حمزہ مسلمان ہوئے حضرت ابوبکر نے صحن کعبہ میں برملا توحید کا اعلان کیا.اس وقت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دوسرے مسلمان بھی وہاں موجود تھے.قریش نے حضرت ابوبکر کی اس
جسارت کو دیکھا تو جوش میں آکر اُن پر ٹوٹ پڑے اور اس بے دردی سے مارا کہ لکھا ہے کہ جب اُن کے
قبیلہ کے لوگ انہیں اُٹھا کر اُن کے گھر لے گئے تو وہ بالکل بے ہوش تھے اور ضربات کی وجہ سے ان کا ناک
منہ ایک ہو رہا تھا.جب انہیں ہوش آیا تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے
اور جب تک آپ کی خیریت کی خبر نہیں سنی حضرت ابو بکر کو چین نہیں آیا ہے
اسلام عمر
ابھی حضرت حمزہ کو اسلام لائے صرف چند دن ہی گذرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
ایک اور خوشی کا موقع دکھایا یعنی حضرت عمرؓ جو ابھی تک اشد مخالفین میں سے تھے مسلمان
ا : طبری وابن ہشام
: الروض الانف لسبیلی
۴ : خمیس جلد اصفحه ۳۳۲
ے : زرقانی
Page 192
122
ہو گئے.ان کے اسلام لانے کا قصہ نہایت دلچسپ ہے.حضرت عمر کی طبیعت میں تختی کا مادہ تو زیادہ تھا ہی
مگر اسلام کی عداوت نے اسے اور بھی زیادہ کر دیا تھا چنانچہ اسلام سے قبل عمر غریب اور کمزور مسلمانوں کو
ان کے اسلام کی وجہ سے بہت سخت تکلیف دیا کرتے تھے لیکن جب وہ انہیں تکلیف دیتے دیتے تھک
گئے اور اُن کے واپس آنے کی کوئی صورت نہ دیکھی تو خیال آیا کہ کیوں نہ اس فتنہ کے بانی کا ہی کام
تمام کر دیا جاوے.یہ خیال آنا تھا کہ تلوار لے کر گھر سے نکلے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع
کی.راستہ میں ایک شخص نے انہیں تنگی تلوار ہاتھ میں لیے جاتے دیکھا تو پوچھا.”عمر! کہاں جاتے ہو؟“
عمر نے جواب دیا.”محمد کا کام تمام کرنے جاتا ہوں.اُس نے کہا کیا تم محمد کو قتل کر کے بنو عبد مناف
سے محفوظ رہ سکو گے؟ ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو.تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں.حضرت
عمر جھٹ پلٹے اور اپنی بہن فاطمہ کے گھر کا راستہ لیا.جب گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن شریف کی
تلاوت کی آواز آئی.جو خباب بن الارت خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے تھے.عمر نے یہ آواز سنی تو
غصہ اور بھی بڑھ گیا.جلدی سے گھر میں داخل ہوئے لیکن ان کی آہٹ سنتے ہی خباب تو جھٹ کہیں چھپ
گئے اور فاطمہ نے قرآن شریف کے اوراق بھی اِدھر اُدھر چھپا دیئے یا حضرت عمر اندر آئے تو للکار کر کہا !
میں نے سنا ہے تم اپنے دین سے پھر گئے ہو.یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید سے لپٹ گئے.فاطمہ
اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو وہ بھی زخمی ہوئیں.مگر فاطمہ نے دلیری کے ساتھ کہا.”ہاں
عمر ! ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے.حضرت عمر نہایت سخت
آدمی تھے لیکن اس سختی کے پردہ کے نیچے محبت اور نرمی کی بھی ایک جھلک تھی جو بعض اوقات اپنا رنگ دکھاتی
تھی.بہن کا یہ دلیرانہ کلام سنا تو آنکھ اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا وہ خون میں تر بہ تر تھی.اس نظارہ کا عمر
کے قلب پر ایک خاص اثر ہوا.کچھ دیر خاموش رہ کر بہن سے کہنے لگے ” مجھے وہ کلام تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے
تھے ؟‘ فاطمہ نے کہا.میں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ تم ان اوراق کو ضائع کر دو گے.‘ عمر نے جواب دیا.نہیں نہیں تم مجھے دکھا دو.میں ضرور واپس کر دوں گا.فاطمہ نے کہا.”مگر تم نجس ہوا اور قرآن کو پاکیزگی
کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہئے.پس تم پہلے غسل کر لو اور پھر دیکھنا.غالباً ان کا منشا یہ بھی ہوگا کہ
غسل کرنے سے عمر کا غصہ بالکل فرو ہو جائے گا اور وہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے قابل ہوسکیں گے.لے : یہ واقعہ یا درکھنے کے قابل ہے کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ابتدائے زمانہ سے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن شریف کو ساتھ ساتھ لکھواتے جاتے تھے اور یہ نسخے متعد دصحابہ کے پاس محفوظ رہتے تھے.منہ
Page 193
KA
جب عمر غسل سے فارغ ہوئے تو فاطمہ نے قرآن کے اوراق نکال کر ان کے سامنے رکھ دیئے.اُنہوں
نے اُٹھا کر دیکھا تو سورۃ طہ کی ابتدائی آیات تھیں.حضرت عمر نے ایک مرعوب دل کے ساتھ انہیں
پڑھنا شروع کیا اور ایک ایک لفظ اس سعید فطرت کے اندر گھر کئے جاتا تھا.پڑھتے پڑھتے حضرت عمرؓ
اس آیت پر پہنچے کہ :
اِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِى إِنَّ السَّاعَةَ
أُتِيَةً أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى LO
یعنی میں ہی اس دنیا کا واحد خالق و مالک ہوں میرے سوا اور کوئی قابل پرستش نہیں.پس تمہیں چاہئے کہ صرف میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لئے اپنی دعاؤں کو وقف
کر دو.دیکھو موعود گھڑی جلد آنے والی ہے مگر ہم اس کے وقت کو مخفی رکھے ہوئے ہیں تا کہ
ہر شخص اپنے کئے کا سچا سچابدلہ پاسکے.“
جب حضرت عمرؓ نے یہ آیت پڑھی تو گویا ان کی آنکھ کھل گئی اور سوئی ہوئی فطرت چونک کر بیدار ہوگئی
بے اختیار ہوکر بولے.” یہ کیسا عجیب اور پاک کلام ہے!
خباب نے یہ الفاظ سنے تو فوراً باہر نکل آئے اور خدا کا شکر ادا کیا اور کہا.” یہ رسول اللہ کی دعا کا نتیجہ
ہے کیونکہ خدا کی قسم ابھی کل ہی میں نے آپ کو یہ دعا کرتے سنا تھا کہ یا اللہ تو عمر ابن الخطاب یا عمرو بن
ہشام ( یعنی ابوجہل ) میں سے کوئی ایک ضرور اسلام کو عطا کر دے.“ حضرت عمرؓ کو اب ایک ایک پل گراں
تھا.خباب سے کہا.” مجھے ابھی محمدصلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتاؤ.مگر کچھ ایسے آپے سے باہر ہورہے تھے
که تلوار اُسی طرح نگی کھینچ رکھی تھی.اس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں مقیم تھے؛ چنانچہ
خباب نے انہیں وہاں کا پتہ بتا دیا.عمر گئے اور دروازہ پر پہنچ کر زور سے دستک دی.صحابہ نے دروازے کی
دراڑ میں سے عمر کونگی تلوار تھامے ہوئے دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تامل کیا.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا.دروازہ کھول دو.“ اور حضرت حمزہ نے بھی کہا.دروازہ کھول دو.اگر نیک ارادہ سے آیا ہے تو
بہتر : ورنہ اگر نیت بد ہے تو واللہ اسی کی تلوار سے اُس کا سراُڑا دوں گا.دروازہ کھولا گیا.عمرنگی تلوار ہاتھ
میں لئے اندر داخل ہوئے.اُن کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا دامن پکڑ کر زور
سے جھٹکا دیا اور کہا: "عمر کس ارادہ سے آئے ہو؟ واللہ میں دیکھتا ہوں کہ تم خدا کے عذاب کے لئے نہیں
ا : سورة طه : ۱۶،۱۵
"
Page 194
129
بنائے گئے.عمر نے عرض کیا.یا رسول اللہ ! میں مسلمان ہونے آیا ہوں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ الفاظ سنے تو خوشی کے جوش میں اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی صحابہ نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ
مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اُٹھیں.حضرت عمر کی عمر اس وقت ۳۳ سال کی تھی اور آپ اپنے قبیلہ بنو عدی کے رئیس تھے.قریش میں
سفارت کا عہدہ بھی انہی کے سپر د تھا اور ویسے بھی نہایت بارعب اور جری اور دلیر تھے.ان کے اسلام
لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت پہنچی اور اُنہوں نے دارارقم سے نکل کر بر ملا مسجد حرام میں نماز ادا کی.حضرت عمرؓ آخری صحابی تھے جو دار ارقم میں ایمان لائے اور یہ بعثت نبوی کے چھٹے سال کے آخری ماہ کا
واقعہ ہے.اس وقت مکہ میں مسلمان مردوں کی تعداد چالیس تھی ہے
جب حضرت عمرؓ کے اسلام کی خبر قریش میں پھیلی تو وہ سخت جوش میں آگئے اور اسی جوش کی حالت میں
اُنہوں نے حضرت عمرؓ کے مکان کا محاصرہ کر لیا.حضرت عمرؓ باہر نکلے تو ان کے اردگر دلوگوں کا ایک بڑا مجمع
اکٹھا ہو گیا اور قریب تھا کہ بعض جو شیلے لوگ اُن پر حملہ آور ہو جائیں لیکن حضرت عمرؓ بھی نہایت دلیری کے
ساتھ ان کے سامنے ڈٹے رہے.آخر اسی حالت میں مکہ کا رئیس اعظم عاص بن وائل اوپر سے آ گیا اور
اس ہجوم کو دیکھ کر اس نے اپنے سردارانہ انداز میں آگے بڑھ کر پوچھا.” یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے
کہا."عمر صابی ہو گیا ہے.اُس نے موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے کہا.” تو خیر پھر بھی اس ہنگامہ کی
ضرورت نہیں.میں عمر کو پناہ دیتا ہوں.اس آواز کے سامنے عربی دستور کے مطابق لوگوں کو خاموش ہونا
پڑا اور وہ آہستہ آہستہ منتشر ہو گئے.اس کے بعد حضرت عمرؓ چند دن تک امن میں رہے کیونکہ عاص بن
وائل کی پناہ کی وجہ سے کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا تھا لیکن اس حالت کو حضرت عمرؓ کی غیرت نے زیادہ دیر
تک برداشت نہ کیا ؛ چنانچہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ انہوں نے عاص بن وائل سے جا کر کہہ دیا کہ
میں تمہاری پناہ سے نکلتا ہوں.حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں مکہ کی گلیوں میں بس پیٹتا
پٹیتا ہی رہتا تھا.مگر حضرت عمرؓ نے کبھی کسی کے سامنے آنکھ نیچی نہیں کی.حضرت عمرؓ کے مسلمان ہونے کے قریب ہی ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر بھی مسلمان ہوئے.ل : ابن ہشام والروض الانف وزرقانی.حضرت عمر کے اسلام کے متعلق بعض اور روایات بھی ہیں.مگر ہم نے
اس جگہ صرف اہل سیرۃ کی معروف روایت کو لے لیا ہے.: زرقانی
: زرقانی
Page 195
۱۸۰
عبداللہ اس وقت بالکل بچہ تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اُنہوں نے بہت بڑا رتبہ
حاصل کیا اور اسلام کے چوٹی کے علماء میں سے سمجھے جانے لگے.جب قریش نے دیکھا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ایک وفد سے ملاقات
رض
کہ حضرت حمزہ اور
حضرت عمر جیسے ذی مقدرت لوگ بھی اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں تو انہیں بہت فکر دامنگیر ہوا اور
اُنہوں نے باہم مشورہ کر کے پہلے تو عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجا تا کہ وہ کسی طرح آپ کو راضی کر
کے اشاعت اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرے لیکن جب عتبہ کو اس مشن میں نا کامی ہوئی بلکہ قریش نے
دیکھا کہ الٹا عتبہ آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر اور مرعوب ہو کر واپس آیا ہے.لے تو انہوں نے ایک
دن کعبہ کے پاس جمع ہو کر باہم مشورہ کیا اور یہ تجویز کی کہ چند رؤسا اکٹھے ہو کر آپ کے ساتھ بات کریں ؛
چنانچہ اس تجویز کے مطابق ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور ابو جہل اور امیہ بن خلف اور عتبہ اور شیبہ اور
ابوسفیان اور اسود بن مطلب اور نضر بن حارث اور ابو البختری وغیرہ صحن کعبہ میں مجلس جما کر بیٹھ گئے
اور ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام دے کر روانہ کیا گیا کہ تمہاری قوم کے رؤساء تم
سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں.تم ذرا صحن کعبہ میں آکر اُن کی بات سن جاؤ.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تو ایسے موقعوں کی تلاش میں خود رہتے تھے، فوراً تشریف لے گئے اور رسمی علیک سلیک کے بعد قریش نے
یوں گفتگو شروع کی کہ " اے محمد ! دیکھو تمہاری وجہ سے قوم میں کتنا اختلاف وانشقاق پیدا ہو رہا ہے.تم
نے اپنے آبا و اجداد کے مذہب میں رخنہ ڈال کر اپنی قوم کے بزرگوں کو بُرا بھلا کہا.ان کے قابل تکریم
معبودوں کو گالیاں دیں اور ان کے ذی عزت بزرگوں کو لا یعقل قرار دیا.اس سے بڑھ کر کسی قوم کی ہتک
اور ذلت کیا ہو سکتی ہے جو تم نے کی ہے اور کر رہے ہو مگر ہم تمہارے معاملہ میں حیران ہیں کہ کیا کریں اور
کیا نہ کریں.اگر تو تمہاری یہ ساری جد و جہد اس غرض سے ہے کہ تم اس ذریعہ سے مال جمع کر کے مالدار
بن جاؤ تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کئے دیتے ہیں کہ تم ہم سب سے زیادہ دولتمند کہلاسکو.اگر جاہ وعزت کی
طلب ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار اور رئیس بنا لینے کے لئے تیار ہیں.اگر حکومت کی حرص ہے تو ہمیں اس میں
بھی تامل نہیں
کہ تمہیں اپنا بادشاہ قرار دے لیں اور اگر تمہارا یہ شور وشغب کسی بیماری یا آسیب کا نتیجہ ہے تو
ہم اپنے پاس سے خرچ کر کے تمہارے علاج کا انتظام کر سکتے ہیں اور اگر تم کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر
لے : ابن ہشام وطبری
Page 196
۱۸۱
کے خوش ہو سکتے ہو تو تمہیں عرب کی بہترین لڑکی تلاش کر کے پیش کیے دیتے ہیں.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خاموشی کے ساتھ رؤسائے قریش کی اس تقریر کوسنا اور جب
وہ اپنی بات ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا: "اے معشر قریش! مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی تمنا نہیں ہے
اور نہ مجھے کوئی آسیب یا بیماری لاحق ہے.میں تو خدا کی طرف سے ایک رسول ہوں اور خدا کا یہ پیغام لے
کر تمہاری طرف آیا ہوں اور میرا دل تمہاری ہمدردی سے معمور ہے.اگر تم میری بات سنو اور مانو تو دین و
دنیا میں تمہارا فائدہ ہے اور اگر تم اسے رڈ کر دو تو میں اس صورت میں صبر و تحمل کے ساتھ اپنے رب کے
فیصلہ کا انتظار کروں گا.قریش نے کہا.” تو اے محمد ! گویا تم ہماری اس تجویز کو منظور نہیں کرتے.اچھا!
اگر تم نے اپنی رسالت ہی منوانی ہے تو آؤ اس کے متعلق فیصلہ کر لو.تم دیکھتے ہو کہ ہمارا یہ ملک کس قدر
بے آب و گیاہ ہے اور خشک پتھروں اور چٹانوں یا ریت کے بے پناہ تو دوں کے سوا یہاں کچھ نظر نہیں آتا.اگر
تم واقعی خدا کے رسول ہو تو اپنے خدا سے کہہ کر اس ملک میں بھی شام و عراق کی طرح نہریں جاری کروا دو
اور ان پہاڑوں کو اڑا کر زرخیز میدان بنوا دو.پھر ہم ضرور تمہاری رسالت کے قائل ہو جائیں گے.آپ
نے فرمایا ”میں تو خدا کی طرف سے ایک پیغامبر ہوں اور میرا کام صرف یہ ہے کہ تمہیں حق و باطل کا راستہ
دکھا دوں اور تمہارے نفع نقصان کی بات تمہیں سمجھا دوں.ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر خدا کی آواز پر
لبیک کہو گے تو خدا اپنے وقت پر ضرور تمہیں دین و دنیا کے انعامات کا وارث بنائے گا.قریش نے کہا اچھا
یہ بھی نہیں تو کم از کم تمہارے ساتھ خدا کا کوئی فرشتہ ہی اُتر تا نظر آتا اور محلات میں تمہارا بسیرا ہوتا اور
تمہارے ہاتھ میں سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے مگر ان میں سے کوئی چیز بھی تو تمہیں میتر نہیں ہے بلکہ ہم
دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرح بازاروں میں پھرتے اور ہماری طرح اپنی روزی کے متلاشی ہوتے ہو.پھر وہ
کونسی علامت ہے جس سے ہم تمہیں خدا کا بھیجا ہوا سمجھ لیں.‘‘ آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا.میں ان باتوں کا اس رنگ میں مدعی نہیں ہوں جو تم ڈھونڈتے ہو.ہاں یہ میں نے کہا ہے اور پھر
کہتا ہوں کہ اگر تم مجھے مانو گے تو خدائی سنت کے مطابق دین و دنیا کی حسنات سے ضرور حصہ پاؤ گے.“
قریش نے بگڑ کر کہا کہ اگر یہ بھی نہیں تو پھر وہ عذاب ہی لاؤ، جس کا تم وعدہ دیتے ہو.آسمان کا کوئی ٹکڑا
ہی ہم پر آ گرے.یا فرشتوں کی کوئی فوج ہی خدائی جھنڈے کے نیچے ہمارے سامنے آدھمکے.خدا کی قسم
ہمیں تو اب بس یہی نظر آ رہا ہے کہ یا ہم زندہ رہیں گے یا تو رہے گا.یہ کہہ کر وہ اپنے غصہ کو دباتے
ہوئے خاموش ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مغموم دل کے ساتھ وہاں سے اُٹھ کر واپس
66
Page 197
۱۸۲
تشریف لے آئے.جب آپ واپس چلے آئے تو ابو جہل نہایت غضبناک ہوکر بولا کہ اے معشر قریش!
تم نے دیکھ لیا کہ محمد نے تمہاری ساری باتوں کو ٹھکرا دیا ہے اور وہ اپنی اس فتنہ انگیزی سے کبھی باز نہیں
آئے گا.اب
واللہ میں بھی اس وقت تک چین نہیں لوں گا کہ جب تک محمد کا سر کچل کر نہ رکھ دوں اور
پھر بنو عبد مناف میرے ساتھ جو کرنا چاہیں کر گزریں.بنو عبد مناف کے جو لوگ وہاں موجود تھے اور
وہ وہی تھے جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ماسوا تھے.ان سب نے بیک آواز کہا.” ہمیں کوئی اعتراض
نہیں ہے.تم محمد کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتے ہو بے شک کرو.دوسرے دن ابو جہل ایک بڑا سا پتھر لے کر
صحن کعبہ کے ایک طرف کھڑا ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا.مگر جب آپ
تشریف لائے تو اس کے دل پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ وہیں بت بن کر کھڑا رہا اور آگے بڑھ کر
وار کرنے کی ہمت نہیں پڑی لے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خداداد رعب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابوجبل
کے مرعوب ہونے کے متعلق ایک اور روایت بھی
آتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ خدائی سنت اسی طرح پر ہے کہ جولوگ خدا کے مرسلین کے سامنے زیادہ
بیباک ہوتے ہیں عموماً انہیں پر خدا تعالیٰ اپنے رسولوں کا رعب زیادہ مسلّط کرتا ہے؛ چنانچہ لکھا ہے کہ
ایک دفعہ اراسته نامی شخص مکہ میں کچھ اونٹ بیچنے آیا اور ابو جہل نے اُس سے یہ اونٹ خرید لیے مگر اونٹوں
پر قبضہ کر لینے کے بعد قیمت ادا کرنے میں حیل و حجت کرنے لگا.اس پر اراشہ جو مکہ میں ایک اجنبی اور
بے یارومددگار تھا بہت پریشان ہوا اور چند دن تک ابو جہل کی منت و سماجت کرنے کے بعد وہ آخر ایک
دن جبکہ بعض رؤسا قریش کعبتہ اللہ کے پاس مجلس جمائے بیٹھے تھے، ان لوگوں کے پاس گیا اور کہنے لگا
اے معززین قریش آپ میں سے ایک شخص ابوالحکم نے میرے اونٹوں کی قیمت دبا رکھی ہے آپ مہربانی
کر کے مجھے یہ قیمت دلوادیں.قریش کو شرارت جو سو جھی تو کہنے لگے ایک شخص یہاں محمد بن عبداللہ نامی
رہتا ہے تم اس کے پاس جاؤ.وہ تمہیں قیمت دلا دے گا اور اس سے غرض ان کی یہ تھی کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم تو بہر حال انکار ہی کریں گے اور اس طرح باہر کے لوگوں میں آپ کی سبکی اور جنسی
ہوگی.جب اراشہ وہاں سے لوٹا تو قریش نے اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی کر دیا کہ دیکھو کیا تماشا بنتا ہے؛
چنانچہ اراشہ اپنی سادگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک مسافر آدمی
ل : ابن ہشام طبری و زرقانی
Page 198
۱۸۳
ہوں اور آپ کے شہر کے ایک رئیس ابوالحکم نے میری رقم دبا رکھی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ مجھے یہ رقم
دلوا سکتے ہیں.پس آپ مہربانی کر کے مجھے میری رقم دلوادیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اُٹھ
کھڑے ہوئے کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں؛ چنانچہ آپ اُسے لے کر ابو جہل کے مکان پر آئے اور
دروازہ پر دستک دی.ابو جہل باہر آیا تو آپ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خاموشی کے ساتھ آپ کا منہ دیکھنے
لگا.آپ نے فرمایا.یہ شخص کہتا ہے کہ اس کے پیسے آپ کی طرف نکلتے ہیں.یہ ایک مسافر ہے آپ اس
کا حق کیوں نہیں دیتے ؟ اس وقت ابو جہل کا رنگ فق ہو رہا تھا.کہنے لگا.”محمد ٹھہر و! میں ابھی اس کی رقم
لاتا ہوں.چنانچہ وہ اندر گیا اور اراشہ کی رقم لا کر اسی وقت اس کے حوالے کر دی.اراشہ نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شکریہ ادا کیا اور واپس آ کر قریش کی اسی مجلس میں پھر گیا اور وہاں جا کر ان کا بھی
شکریہ ادا کیا کہ آپ لوگوں نے مجھے ایک بہت ہی اچھے آدمی کا پتہ بتایا.خدا اسے جزاء خیر دے اُس نے
اُسی وقت میری رقم دلا دی.رؤساء قریش کے منہ میں زبان بند تھی اور وہ ایک دوسرے کی طرف حیران ہو
کر دیکھ رہے تھے.جب اراشہ چلا گیا تو انہوں نے اس آدمی سے دریافت کیا جو اراشہ کے پیچھے پیچھے
ابو جہل کے مکان تک گیا تھا کہ کیا قصہ ہوا ہے.اُس نے کہا.واللہ ! میں نے تو ایک عجیب نظارہ دیکھا
ہے اور وہ یہ کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جا کر ابوالحکام کے دروازہ پر دستک دی اور ابوالحکام نے باہر
آکر محمد کو دیکھا تو اسوقت اس کی حالت ایسی تھی کہ گویا ایک قالب بے روح ہے اور جو نہی کہ اسے محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم ) نے کہا کہ اس کی رقم ادا کر دو، اُسی وقت اُس نے اندر سے پائی پائی لا کر سامنے رکھ
دی.تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل بھی اس مجلس میں آپہنچا.اسے دیکھتے ہی سب لوگ اس کے پیچھے ہو
لیے کہ اے ابوالحکم تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ محمد سے اس قدر ڈر گئے.اُس نے کہا.خدا کی قسم ! جب میں نے محمد
کو اپنے دروازے پر دیکھا، تو مجھے یوں نظر آیا کہ اُس کے ساتھ لگا ہوا ایک مست اور غضبناک اُونٹ کھڑا
ہے اور میں سمجھتا تھا کہ اگر ذرا بھی چون و چرا کروں
گا تو وہ مجھے چہا جائے گا لیے
جو الزامات قریش مکہ کی طرف سے
ایک عیسائی غلام سے تعلیم حاصل کرنے کا الزام ہم محضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
لگائے جاتے تھے اُن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ بعض عیسائیوں سے باتیں سیکھتے ہیں اور پھر انہیں اپنا
رنگ دے کر اپنی تعلیم کے طور پر پیش کر دیتے ہیں.اس ضمن میں خاص طور پر ایک جبو نامی عیسائی کا نام لیا
ل سيرة ابن ہشام
Page 199
۱۸۴
جاتا تھا جو مکہ کے ایک مشرک رئیس ابن حضرمی کا غلام تھا.یہ شخص چونکہ عیسائی تھا اور عیسائیت کی تعلیم
بت پرستی کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب تھی اور مکہ کے مناظر میں جبر کو شرک اور بت پرستی کے سوا کچھ
نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ کبھی کبھی اپنے مذہبی شوق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا رہتا تھا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے شوق کو دیکھ کر کبھی کبھی اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور
اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے.قریش نے یہ نظارہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی غرض
سے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ ”محمد تو جبر سے تعلیم حاصل کرتا ہے.اسلام اور مسیحیت کی تعلیم کے
اختلاف اور جبر کی علمی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ ایک نہایت فضول اور لغو اعتراض تھا، مگر قریش کو تو صرف
اعتراض کی ضرورت تھی.معقول یا غیر معقول ہونے سے سروکار نہ تھا.اس لیے وہ بڑے شوق سے اس
اعتراض کو دوہراتے رہے.قرآن شریف نے اس اعتراض کا خوب جواب دیا ہے کہ جس شخص کی طرف تم
محمد رسول اللہ کی تعلیم کو منسوب کرتے ہو اس کی زبان تو ظاہری اور معنوی ہر دورنگ میں گنگ ہے، پھر وہ
قرآن جیسی کتاب میں محمد رسول اللہ کا استاد کس طرح ہو سکتا ہے یا یعنی یہ شخص غیر عربی ہونے کی وجہ سے
اس فصیح اور بلیغ عربی کلام کا معلم کس طرح سمجھا جا سکتا ہے جو قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے اور دوسری
طرف معنوی رنگ میں اس شخص کی جہالت معارف قرآنی کا سر چشمہ کس طرح قرار دی جاسکتی ہے.قرآنی آیات محولہ بالا میں جو عجمی یعنی غیر عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے یہ مراد بھی ہوسکتی ہے کہ
چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ابھی انا جیل کا عربی ترجمہ نہیں ہوا تھا.اس لیے اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرانا جیل کے کوئی حصے سناتا ہوگا تو وہ لاز ما عبرانی یا یونانی میں ہوں گے.پھر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کس طرح سمجھتے اور کس طرح عربی کے قالب میں ڈھالتے ہوں گے.بعض روایتوں میں جبر کے سوا بعض اور لوگوں کے نام بھی اس تعلق میں بیان ہوئے ہیں جن کے
متعلق قریش اعتراض کیا کرتے تھے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسکھاتے ہیں.مگر لطیفہ یہ ہے کہ یہ
سب لوگ غلاموں کے طبقہ میں سے تھے.بہر حال قریش مکہ نے کچھ دن اس اعتراض کو شہرت دے کر
بھی اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی مگر جو آگ نہ بجھنے والی تھی وہ کیسے بجھتی ؟
: سورة نحل
ا : ابن ہشام
: دیکھو ٹیکسٹ اینڈ کمین آف نیوٹسٹیمنٹ مصنفہ اے سوٹر ایم.اے اور شائع کردہ میسر زڈ کو رتھ لندن صفحہ ۷۲
: تفسیر البحر المحیط زیر آیت ۱۰۴ سورۃ نحل.نیز لائف آف محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) مصنفہ سرولیم میور صفحه ۶۵
Page 200
۱۸۵
ابتر ہونے کا الزام انہی ایام میں بعض قریش نے یہ کہہ کر بھی اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ
محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) تو لا وارث اور بے نسل ہے.چند دن تک اس کا سلسلہ
خود بخود ختم ہو جائے گا.اس پر یہ وحی نازل ہوئی کہ :
إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَةُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْلُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ! ہم نے تیری نسل اور تیری برکات و فیض کے سلسلہ کو بہت
لمبا بنایا ہے.پس تو خدا کے لیے اپنے نفس کی طاقتوں اور اپنی نسل و اموال کو بیشک بے دریغ
خرچ کر.کیونکہ یہ خزانہ ختم ہونے والا نہیں ہے؛ البتہ تیرے بدخواہ دشمنوں کے سارے سلسلے
مٹا دیے جائیں گے.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس شاندار اور آپ کے معاندین کے لیے جس ہیبت ناک
طریق پر آپ کا یہ الہام پورا ہوا ہے وہ تاریخ کا ایک کھلا ورق ہے جسے کسی تشریح کی ضرورت نہیں.انہی
اعتراض کرنے والوں کی اولا د نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو کر اس بات
پر مہر لگا دی کہ نہ صرف قریش بلکہ تمام قبائل عرب میں سے اگر کسی شخص کی نسل حقیقتاً قائم رہی ہے تو وہ
صرف محمد رسول اللہ ہیں.وو
قریش کی طرف سے مصالحت کی تجویز جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان ایام میں قریش سخت
پیچ و تاب کھا رہے تھے اور ہر شخص اس سوچ میں پڑا ہوا
تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا کس طرح مقابلہ کیا جائے.اس ادھیڑ بن میں
ایک دن روسائے قریش میں سے ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور امیہ بن خلف وغیرہ آپس میں بات
کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے.اے محمد! یہ اختلاف تو بہت بڑھتا جاتا ہے
اور ہمارا قومی شیرازہ بکھر رہا ہے.کیا کوئی باہم مصالحت کی تدبیر نہیں ہو سکتی؟ آپ نے دریافت فرمایا.وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور تم اپنی عبادت کو مشترک کر لیتے ہیں یعنی تم اپنے خدا کے ساتھ
ہمارے بتوں کو بھی پوج لیا کرو اور ہم اپنے بتوں کی عبادت میں تمہارے خدا کو بھی شریک کر لیا کریں
گے.اس طرح مصالحت سے ایک یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ہم میں سے جو فریق حق اور راستی پر ہے اس کا فائدہ
دوسرے کو بھی پہنچتا رہے گا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا.ذرا غور تو کرو یہ کس طرح ہوسکتا
لے سورۃ کوثر اور ابن ہشام
Page 201
۱۸۶
ہے؟ میں اپنے خدا کو مانتے ہوئے تمہارے بتوں کو کس طرح پوج سکتا ہوں اور تم بت پرستی پر قائم رہتے
ہوئے میرے خدا کی پرستش کس طرح کر سکتے ہو؟ یہ دونوں باتیں تو ایک دوسرے کے اس قد ر مخالف اور
متضاد واقع ہوئی ہیں کہ کسی طرح ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں.چنانچہ انہی ایام میں قرآن شریف کی یہ
آیات نازل ہوئیں کہ :
قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عُبِدُونَ مَا أَعْبُدُ
،
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا انْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُهُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِى دِينِ
د یعنی اسے کفار کے گروہ! جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں انہیں قابل پرستش نہیں سمجھتا اور
نہ تم اپنے بتوں کو پوجتے ہوئے میرے خدا کی پرستش کر سکتے ہو.پس یہ ناممکن ہے کہ میں کبھی
تمہارے بتوں کی پرستش کروں جس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ تم اپنے بتوں پر ایمان لاتے ہوئے
میرے وحدہ لاشریک خدا کے سامنے جھکو.میرا دین اور ہے اور تمہارا دین اور ہے اور یہ دونوں
کبھی بھی ایک جگہ مل نہیں سکتے.“
اس جواب سے قریش نے سمجھ لیا کہ ان کے اس ہوائی قلعہ کے کوئی پاؤں نہیں ہیں.مسلمانوں کے خلاف قریش کا معاہدہ اور مسلمانوں کا بائیکاٹ قریش کو ان کی اوپر تلے
کی ناکامی نے سخت
مشتعل کر دیا تھا.سب سے اول ابوطالب کے معاملہ میں انہیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑا اور وہ بنو ہاشم کو
مسلمانوں سے جدا نہ کر سکے.اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح کے مصائب و آلام میں مبتلا
کر کے دیکھ لیا کہ یہ چٹان اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہے.بعدہ حضرت حمزہ اور حضرت عمرؓ کے اسلام نے
ان کی آنکھیں اس حقیقت کے دیکھنے کے لیے کھول دیں کہ شروع شروع میں مخالف رہنے کے بعد بھی ان
کے بڑے سے بڑے لوگ اسلام کی رو میں بہہ جانے سے محفوظ نہیں ہیں.زاں بعد حبشہ کا وفد نجاشی کے
دربار سے خائب و خاسر ہو کر لوٹا اور قریش کو اس معاملہ میں سخت ذلت نصیب ہوئی اور اب انہوں نے خود
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ جنبانی کر کے ایسی منہ کی کھائی کہ باید و شاید.ان پے در پے
ناکامیوں اور ذلتوں نے قریش کے تن بدن میں آگ لگادی تھی ، چنانچہ انہوں نے ایک عملی اقدام کے طور
پر باہم مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام افراد بنو ہاشم اور بنومطلب کے ساتھ ہر قسم
: سورۃ کافرون وسيرة ابن ہشام
: طبری
Page 202
۱۸۷
کے تعلقات قطع کر دئیے جاویں اور اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سے دستبردار نہ ہوں تو ان کو
ایک جگہ محصور کر کے تباہ کر دیا جاوے؛ چنانچہ محرم ۷ نبوی میں ایک با قاعدہ معاہدہ لکھا گیا کہ کوئی شخص
خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب سے رشتہ نہیں کرے گا اور نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کرے گا.نہ اُن
سے کچھ خریدے گا اور نہ اُن کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز جانے دے گا اور نہ اُن سے کسی قسم کا تعلق
رکھے گا.جب تک کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے الگ ہو کر آپ کو ان کے حوالے نہ کر دیں سے یہ معاہدہ
جس میں قریش کے ساتھ قبائل بنو کنانہ بھی شامل تھے.کے باقاعدہ لکھا گیا اور تمام بڑے بڑے رؤساء کے
اُس پر دستخط ہوئے اور پھر وہ ایک اہم قومی عہد نامہ کے طور پر کعبہ کی دیوار کے ساتھ آویزاں کر دیا گیا؟
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کیا مسلم اور کیا کافر (سوائے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے چا ابولہب کے جس نے اپنی عداوت کے جوش میں قریش کا ساتھ دیا ) شعب ابی طالب
میں جو ایک پہاڑی درہ کی صورت میں تھا، محصور ہو گئے اور اس طرح گویا قریش کے دو بڑے قبیلے مکہ کی
حمد نی زندگی سے عملاً بالکل منقطع ہو گئے اور شعب ابی طالب میں جو گویا بنو ہاشم کا خاندانی درہ تھا
قیدیوں کی طرح نظر بند کر دیئے گئے." چند گنتی کے دوسرے مسلمان جو اس وقت مکہ میں موجود تھے
وہ بھی آپ کے ساتھ تھے.جو جو مصائب اور سختیاں ان ایام میں ان محصورین کو اُٹھانی پڑیں اُن کا حال پڑھ کر بدن پر لرزہ پڑ جاتا
ہے.صحابہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات اُنہوں نے جانوروں کی طرح جنگلی درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارہ
کیا.سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت ان کا پاؤں کسی ایسی چیز پر جا پڑا جو
تر اور نرم معلوم ہوئی تھی (غالباً کوئی کھجور کا ٹکڑا ہو گا ).اس وقت ان کی بھوک کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے فوراً
اُسے اٹھا کر نگل لیا اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آج تک پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز تھی.ایک دوسرے موقع پر
بھوک کی وجہ سے ان کا یہ حال تھا کہ انہیں ایک سوکھا ہوا چھڑا زمین پر پڑا ہوا مل گیا تو اُسی کو اُنہوں نے
پانی میں نرم اور صاف کیا اور پھر بھون کر کھایا اور تین دن اسی غیبی ضیافت میں بسر کئے.بچوں کی یہ حالت
تھی کہ محلہ سے باہر ان کے رونے اور چلانے کی آواز جاتی تھی جسے سن سن کر قریش خوش ہوتے ہے لیکن
ا : ابن سعد
: طبری ابن سعد وابن ہشام
ے : ابن ہشام وابن سعد وطبری سے : بخاری کتاب وجوب الحج
: کتب احادیث بحوالہ الروض الانف
: الروض الانف حالات نقض صحیفہ کے : ابن سعد ذکر حصر قریش
Page 203
۱۸۸
مخالفین اسلام سب ایک سے نہ تھے.بعض یہ درد ناک نظارے دیکھتے تھے تو ان کے دل میں رحم پیدا ہوتا
تھا.چنانچہ حکیم بن حزام کبھی کبھی اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے خفیہ خفیہ کھانا لے جاتے تھے.مگر ایک
دفعہ ابو جہل کو کسی طرح اس کا علم ہو گیا تو اس کمبخت نے راستہ میں بڑی سختی کے ساتھ روکا اور باہم ہاتھا پائی
تک نوبت پہنچ گئی یا یہ مصیبت برابراڑھائی تین سال تک جاری رہی اور اس عرصہ میں مسلمان سوائے حج
وغیرہ کے موسم کے جب کہ اشہر حرم کی وجہ سے امن ہوتا تھا باہر نہیں نکل سکتے تھے ہے
اس ظلم سے مسلمانوں کی رہائی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے قریش میں بعض نرم دل اور شریف
مزاج لوگ بھی تھے.یہ لوگ ان مظالم کو دیکھتے تو دل میں
گڑھتے مگر قوم کے متفقہ فیصلہ کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتے تھے، اس لیے دل ہی دل میں بیچ و تاب کھا کر رہ
جاتے آخر خدا کی طرف سے ایسا سامان پیدا ہو گیا کہ انہیں اس معاملہ میں جرات کے ساتھ قدم اُٹھانے کی
ہمت پڑ گئی.اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ جب اس بائیکاٹ پر قریباً تین سال کا عرصہ گذر گیا، تو
ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چا ابو طالب سے فرمایا کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ ہمارے
خلاف جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس میں سوائے خدا کے نام کے ساری تحریر مٹ چکی ہے اور کاغذ کھایا جاچکا
ہے.ابو طالب فورا اٹھ کر خانہ کعبہ میں پہنچے جہاں بہت سے رؤسائے قریش مجلس لگائے بیٹھے تھے اور ان کو
مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تمہارا یہ ظالمانہ معاہدہ کب تک چلے گا.میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ خدا نے
اس معاہدہ کی ساری تحریر سوائے اپنے نام کے محو کر دی ہے یا تم ذرا یہ معاہدہ نکالو تا کہ دیکھیں کہ میرے
بھتیجے کی یہ بات کہاں تک درست ہے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں ! ضرور دیکھنا چاہیے.چنانچہ معاہدہ منگا کر دیکھا گیا تو واقعی وہ سب کرم خوردہ ہو چکا تھا اور سوائے شروع میں خدا کے نام کے
کوئی لفظ پڑھا نہیں جاتا تھا.اس پر بعض قریش تو اور بھی زیادہ چمک اُٹھے لیکن وہ جن کے دل میں پہلے
سے انصاف اور رحم اور قرابت داری کے جذبات پیدا ہو رہے تھے ان کو اس معاہدہ کے خلاف آواز
اٹھانے کا ایک عمدہ موقع ہاتھ آ گیا ہے چنانچہ روسائے قریش میں سے ہشام بن عمرو.زہیر بن ابی امیہ.مطعم بن عدی.ابوالبختری اور زمعہ بن اسود نے باہم مل کر یہ تجویز کی کہ اس ظالمانہ اور قطع رحمی کرنے
ل : ابن ہشام
: ابن سعد
: قریش کی عادت تھی کہ اپنی تحریرات کے شروع میں باسمک اللھم کے لفظ لکھا کرتے تھے اور معاہدہ میں
صرف یہی حصہ باقی رہ گیا تھا.: ابن ہشام وابن سعد
Page 204
۱۸۹
والے معاہدہ کو اب ختم کر دینا چاہئے.یہ تجویز کر کے یہ لوگ دوسرے رؤساء قریش کی مجلس میں گئے اور ان
میں سے ایک نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا ”اے قریش کیا یہ مناسب ہے کہ تم تو مزے کے ساتھ زندگی
بسر کرو اور تمہارے بھائی اس طرح مصیبت میں دن کا ئیں.یہ معاہدہ ظالمانہ ہے اسے اب منسوخ کر دینا
چاہیئے.اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس کی تائید کی.لیکن ابو جہل بولا : ”ہر گز نہیں یہ معاہدہ قائم
رہے گا اسے کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا.کسی نے جواب دیا.”نہیں اب یہ قائم نہیں رہ سکتا.جب یہ لکھا
گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے.اسی حیل و حجت میں مطعم بن عدی نے ہاتھ بڑھا کر یہ بوسیدہ
دستاویز چاک کر دی اور ابو جہل اور اس کے ساتھی دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے.صحیفہ چاک کرنے کے بعد یہ لوگ ہتھیار لگا کر شعب ابی طالب کے دروازہ پر گئے اور تلواروں
کے سایہ کے نیچے محصورین کو باہر نکال لائے.یہ واقعہ بعثت نبوی کے دسویں سال کا ہے یا گویا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اڑھائی تین سال تک محصور رہے کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے.آپ بعثت کے ساتویں
سال ماہ محرم میں محصور ہوئے تھے.شق القمر کا معجزہ غالبا ابھی آپ شعب ابی طالب میں ہی تھے کہ شق القمر کا مشہور معجزہ ظاہر ہوا یعنی
بعض کفار مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب کیا اور آپ نے
انہیں چاند کے دوٹکڑے ہو جانے کا معجزہ دکھایا.اس واقعہ کا قرآن شریف میں اس طرح ذکر آتا ہے:
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا أَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا
سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِنُّ وَلَقَدْ
جَاءَهُم مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرَّه
موعود گھڑی قریب آگئی ہے اور چاند پھٹ گیا.اگر یہ لوگ کوئی نشان دیکھیں تو منہ پھیر
لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے اور ایسا جادو ہوتا ہی چلا آیا ہے.انہوں نے ہمارے
رسول کی تکذیب کی اور اپنی حرص و آز کے پیچھے پڑے رہے؛ حالانکہ ہر بات کا وقت مقرر ہوتا
ہے.بہر حال ہم نے انہیں ایک ایسی خبر پہنچادی ہے جس میں ان کے لیے ایک تنبیہ اور بیداری
کا سامان موجود ہے.اور حدیث میں اس معجزہ کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے:
ا : ابن سعد
۲ : سورة قمر : ۲ تا ۵
Page 205
۱۹۰
إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ الله أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ
شَقَّتَيْن حَتَّى رَأَوْ حِرَاءً بَيْنَهُمَا
یعنی کفار مکہ نے آپ سے کوئی معجزہ طلب کیا جس پر آپ نے انہیں چاند کو دوٹکڑوں
میں دکھایا.حتی کہ انہیں چاند کا ایک ٹکڑا حراء پہاڑی کے ایک طرف نظر آتا تھا اور دوسرا
دوسری طرف.“
اور ایک دوسری روایت میں جو عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے یہ الفاظ ہیں :
انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِي الله
الله بِمَنِى فَقَالَ اشْهَدُوا.....فِرْقَةٌ
فَوقَ الْجَبَلِ وَفِرْقَةٌ دُونَهُ
یعنی ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منیٰ میں تھے کہ چاند دوٹکڑے ہو گیا.جس پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اور گواہ رہو.ایک ٹکڑا پہاڑی کے اوپر کی جانب تھا
اور دوسرا نیچے کی طرف.“
اس کے علاوہ حدیث اور کتب سیرۃ میں شق القمر کے متعلق اور بھی بہت سی روایات ہیں جن میں بعض
مزید تفصیلات بھی دی گئی ہیں مگر زیادہ معتبر روایات وہی ہیں جو او پر درج کر دی گئی ہیں.علاوہ ازیں چونکہ
ہمیں اس جگہ اس مسئلے کے متعلق مناظرانہ رنگ میں کوئی بحث کرنا مقصود نہیں اس لیے اس موقع پر صرف
مندرجہ بالا روایات کا اندراج کافی ہے؛ البتہ ایک مختصر تشریحی نوٹ اس بات کے متعلق درج کرنا ضروری
ہے کہ اس معجزہ کی حقیقت کیا تھی.آیا واقعی چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھایا یہ کہ صرف دیکھنے والوں کی نظروں پر
ایسا تصرف ہوا کہ چاند انہیں دوٹکڑوں میں نظر آیا.نیز یہ کہ اس معجزہ کی غرض وغایت کیا تھی ؟
سواس کے متعلق جاننا چاہیئے کہ گو خدا کی قدرت کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں اور جو شخص یہ
ایمان رکھتا ہے کہ یہ سارا عالم خدا کے دست قدرت سے عالم وجود میں آیا ہے وہ اس بات کے ماننے میں
ایک لمحہ کے لیے بھی تامل نہیں کر سکتا کہ اگر خدا چاہے تو اپنے ایک اشارہ سے اس کے سارے تار و پود کو
ملیا میٹ کر کے رکھ دے مگر جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے ثابت شدہ بات یہی ہے کہ چاند حقیقتا دوٹکڑے نہیں
ہوا بلکہ خدائی تصرف کے ماتحت صرف دیکھنے والوں کو دوٹکڑوں میں نظر آیا تھا اور یہ کوئی تعجب انگیز بات
نہیں کیونکہ جب کہ ایک مشاق انسان اپنی قوت ارادی یعنی پینوٹزم کے زور سے دوسروں کو ایک مرئی چیز
ل ، ۲ : بخاری ومسلم
Page 206
۱۹۱
اپنی غیر اصلی صورت میں دکھا سکتا ہے تو خدا کی قدرت اور اس کے رسول کی روحانی طاقت کے آگے تو یہ
بات کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی کہ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھوں پر ایسا تصرف ہوا ہو کہ انہیں چاند دو
ٹکڑوں میں پھٹتا نظر آیا ہو.بہر حال ہمارے نزدیک اصل حقیقت یہی ہے کہ چاند حقیقہ دوٹکڑے نہیں ہوا
تھا بلکہ صرف دیکھنے والوں
کو دوٹکڑوں میں نظر آیا تھا اور اگر غور کیا جاوے تو حدیث کے الفاظ بھی اسی طرف
اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ایک تصرف الہی تھا جو دیکھنے والوں کی نظروں پر کیا گیا اور اکثر محققین نے اسی تشریح
کو صحیح قرار دیا ہے لیکن اگر بالفرض اس معجزہ کو اس کی ظاہری صورت میں بھی قبول کیا جائے تو پھر بھی ہرگز
جائے اعتراض نہیں.اللہ تعالیٰ کی قدرتیں لامحدود ہیں جن کی معمولی وسعت تک بھی انسان کی نظر نہیں
پہنچ سکتی.ابھی ۱۹۲۸ء کا واقعہ ہے کہ جنوبی امریکہ کے ملک لا پلاٹا میں ایک ستارہ دوٹکڑے ہوتا دیکھا گیا.اس ستارے کا نام نو وا پکٹورس (Nova Pictoris) تھا جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی رصد گاہ واقع
جونس برگ نے بھی اس واقعہ کی تصدیق کی ہے اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس
سے پہلے بھی کوئی آسمانی ستارہ دو ٹکڑے ہو گیا ہو یا پس کوئی تعجب نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانہ میں خدائی تصرف کے ماتحت چاند میں سے کوئی ٹکڑا الگ ہو گیا ہو یا چاند دوٹکڑے ہو کر پھر مل گیا ہوا اور
کوئی سائنسدان اس پر اعتراض نہیں کر سکتا لیکن حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے.واللہ اعلم
اب رہا دوسرا سوال کہ اس معجزہ کی غرض و غایت کیا تھی اور دراصل اس بحث میں یہی اصل اور اہم
سوال ہے کیونکہ اسی سے اس معجزہ کی حقیقت اور شان ظاہر ہو سکتی ہے.سواس کے متعلق جاننا چاہئے کہ
دراصل علم تعبیر رویا میں چاند سے حکومت و بادشاہ مراد ہوتے ہیں.خواہ وہ عادل وانصاف پسند ہوں یا کہ
ظالم و جابر ے اور اس تاویل کی متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں ؛ چنانچہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب
خیبر کے یہودی رئیس حیی بن اخطب کی لڑکی صفیہ نے یہ خواب دیکھا کہ چاند اس کی گود میں آگرا ہے تو
اس کے باپ نے اس کی یہی تعبیر کی تھی کہ صفیہ کسی دن عربوں کے بادشاہ کے عقد میں آئے گی ؛ چنانچہ ایسا
ہی ہوا کہ فتح خیبر کے بعد صفیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی.اسی طرح جب حضرت عائشہ
نے خواب دیکھا کہ ان کے حجرے میں تین چاند آگرے ہیں تو واقعات نے اس خواب کی یہی تعبیر ثابت
کی کہ اس سے اُن کے حجرے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت
ابو بکر اور حضرت
عمرؓ کا دفن ہونا مراد
دیکھو ہندوستان ٹائمنر دہلی مؤرخہ ۲۹ را پریل ۱۹۲۸ء
: دیکھو تعطیر الانام جلد ۲ زیر لفظ قمر
۳ : اسدالغا به وزرقانی حالات صفیه
Page 207
۱۹۲
ہے.اس صورت میں گویا کفار مکہ کو چاند کے دوٹکڑے ہو جانے کا معجزہ دکھانے میں یہ اشارہ تھا کہ اب
تمہاری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس کی جگہ اسلامی حکومت قائم ہوگی.گویا جب کفار قریش نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کی نظروں میں چاند کو دوٹکڑے کر کے
زبانِ حال سے بتا دیا کہ تم مجزہ مانگتے ہو اور یہاں تمہاری موت کی گھنٹی بج رہی ہے.چنانچہ قرآن شریف
نے اس معجزہ کے بیان کے ساتھ جو اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (یعنی تمہاری قیامت قریب آ گئی ہے ) کے
الفاظ استعمال کئے ہیں ان میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے.گویا جب کفار نے معجزہ مانگا
تو انہیں جواب میں شق القمر کا معجزہ دکھا کر یہ بتایا گیا کہ اب تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو کر محمد رسول اللہ کی
حکومت کا دور دورہ شروع ہونے والا ہے جو آپ کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ہو گا اور چونکہ کفارا اپنی
روایات کی بنا پر اس اشارے کو سمجھتے تھے وہ بے اختیار ہو کر بول اُٹھے کہ سحر مستمر یعنی اے محمد ! اگر
تمہاری موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے ایسا ہو گیا تو پھر یہ ایک بڑا پکا جادو ہو گا.الغرض شق القمر کے معجزہ میں
اصل غرض و غایت یہی تھی کہ کفار مکہ کو بتایا جائے کہ اب تمہاری حکومت کا خاتمہ ہے.اسی تشریح کے ساتھ
شق ایک عظیم الشان معجزہ قرار پاتا ہے؛ ورنہ محض ظاہر میں بے نتیجہ طور پر چاند کا دوٹکڑے ہو جانا گوعلم ہیئت
کی رو سے ایک عجوبہ ہومگر روحانی رنگ میں اس کا کوئی وزن نہیں.اسی لیے گذشتہ علماء میں سے بھی امام
غزالی اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جیسے محققین نے یہی خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ صرف ایک خدائی
تصرف تھا جس کے ماتحت کفار کو چاند دو ٹکڑوں میں ہو کر نظر آیا؛ ورنہ حقیقت میں چاند دوٹکڑے نہیں ہوا
تھائے اور جب حقیقہ چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا بلکہ صرف دیکھنے والوں کو ایسا دکھائی دیا تو لامحالہ اس میں کوئی
خاص حکمت ہوگی اور وہ حکمت وہی تھی جو ہم نے اوپر بیان کی ہے.واللہ اعلم.شق القمر کا معجزہ ہجرت
سے قریباً پانچ سال قبل 9 نبوی میں ہوا تھا.ہے
حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات جب آپ شعب ابی طالب سے نکلے تو آپ کو پے در پے
دو نہایت شدید صدمے پہنچے.یعنی حضرت خدیجہ اور
ابوطالب یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے.یہ دونوں عمر رسیدہ تھے اور وفات ہر انسان کے لئے مقدر ہے
لیکن ان دونوں کا شعب ابی طالب میں محصور ہونے کے زمانہ کے اس قدر قریب فوت ہونا اس بات کا
ل : مؤطا امام مالک کتاب الجنائز
ے : سیرة النبی جلد سوم
: خمیس
: مفصل بحث کے لئے دیکھئے سرمہ چشم آریہ.مصنفہ مقدس بانی سلسلہ احمدیہ
Page 208
۱۹۳
قوی شبہ پیدا کرتا ہے کہ محصور ہونے کی غیر معمولی تختی کا ان کی وفات میں بہت کچھ دخل تھا اور ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ مسلسل تختی کے اثر کے نیچے اُن کی صحتیں بالکل شکستہ ہوگئی تھیں لیکن جب تک تو وہ محصور رہے ان کی
طبیعتوں کو مقابلہ کے خیال نے سنبھالے رکھا مگر جو نہی کہ وہ باہر آئے محاصرہ کی لمبی سختی نے اپنا اثر ظاہر کر دیا
اور دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے موت کا شکار ہو گئے.ان پے در پے صدموں کی وجہ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال یعنی ۱۰ نبوی کا نام عام الحزن یعنی غموں کا سال رکھا.ابوطالب گویا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور باپ کے تھے اور آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو بھی
ان سے بہت محبت تھی.جب ابو طالب مرض الموت میں تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم با قاعدہ ان کے
پاس تشریف لے جایا کرتے تھے؛ چنانچہ ایک دفعہ جب ان کی وفات قریب تھی.آپ اُن کے پاس
تشریف لے گئے.اس وقت وہاں ابو جہل وغیرہ مشرکین بھی بیٹھے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابوطالب کی وفات قریب دیکھ کر فرمایا.” چا! آپ صرف کلمہ شہادت پڑھ دیں.میں قیامت کے دن
خدا کے حضور آپ کے متعلق عرض کروں گا.“ یہ سن کر ابو جہل وغیرہ گھبرائے اور ابوطالب سے کہنے لگے کہ
کیا آپ اپنے والد عبدالمطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ اور مختلف صورتوں میں ابوطالب کو سمجھاتے رہے
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابوطالب کی زبان سے جو آخری الفاظ سنے گئے وہ یہ تھے کہ ”میں عبد المطلب کے دین
پر مرتا ہوں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو دردمند ہو کر فرمایا.”اچھا میں بھی اپنے رب
سے آپ کے واسطے مغفرت چاہتا رہوں گا سوائے اس کے کہ میں اس سے روک دیا جاؤں.مگر ابھی
زیادہ وقت نہیں گذرا تھا کہ آپ اس سے روک دیئے گئے اور شرک اور کفر پر مرنے والوں کے لیے یہ حکم
نازل ہوا کہ اُن کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں بلکہ ان کا معاملہ خدا پر چھوڑ نا چاہیئے کے
ایک روایت یہ بھی آتی ہے جو بعید نہیں کہ درست ہو کہ ابو طالب نے مرتے ہوئے رؤسا قریش سے
یہ الفاظ کہے کہ : ”اے قریش کے گروہ ! تم خدا کی خلق میں ایک برگزیدہ قوم ہوا اور خدا نے تمہیں بڑی عزت
دی ہے.میں تمہیں محمد کے متعلق نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ تم میں ایک اعلیٰ
اخلاق کا انسان ہے اور عربوں میں اپنے صدق اور سداد کی وجہ سے امتیاز رکھتا ہے اور سچ پوچھو تو وہ ہماری
طرف وہ پیغام لایا ہے جس سے خواہ زبان انکار کرتی ہے، مگر دل اُسے مانتا ہے.میں نے عمر بھر محمد کا ساتھ
دیا ہے اور ہر تکلیف کے موقع پر اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا ہوں اور اگر مجھے اور مہلت ملی تو آئندہ
: بخاری باب قصه ابی طالب
: زرقانی
Page 209
۱۹۴
بھی ایسا ہی کروں گا اور اے قریش! میری تمہیں بھی یہ نصیحت ہے کہ اسے دکھ دینے کے درپے نہ ہو بلکہ اس
کی نصرت اور اعانت کرو کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے.اس کے بعد ابو طالب کی جلد ہی وفات ہوگئی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات پر سخت صدمہ ہوا اور چونکہ ابو طالب ہمیشہ قریش کے مقابل میں
آپ کے حامی اور محافظ رہے تھے، اس لیے ان کی وفات سے آپ کی پوزیشن اور بھی زیادہ نازک ہو گئی.وفات کے وقت جو انبوی میں واقع ہوئی ابو طالب کی عمر اسی سال سے اوپر تھی..ابو طالب گوزندگی بھر
شرک پر قائم رہے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہیں اپنے
باپ کی طرح سمجھا اور ان کی محبت و وفاداری اور خدمت واطاعت اور عزت واحترام کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھایا
جس کی نظیر نہیں ملتی.دوسری طرف ابو طالب نے بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہایت درجہ مربیانہ اور وفادارانہ
سلوک رکھا اور اپنے آپ کو ہر قسم کی تکلیف میں ڈالنا گوارا کیا مگر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا.ان کا یہ سلوک
جہاں اُن کی اپنی شرافت و وفاداری کا ثبوت ہے وہاں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ خواہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشر کا نہ خیالات کے ماتحت غلطی خوردہ خیال کرتے ہوں مگر جھوٹا اور
دھوکا دینے والا ہر گز نہیں سمجھتے تھے اور آپ کے اعلیٰ اخلاق اور راست گفتاری اور اخلاص کے دل سے قائل
تھے ، چنانچہ اس موقع پر میور صاحب لکھتے ہیں :
’ابو طالب نے باوجود اپنے بھتیجے کے مشن پر ایمان نہ لانے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
خاطر جس رنگ میں ہر قسم کی تکلیف برداشت کی اور جس طرح اپنی ذات اور اپنے خاندان کو
اپنے بھتیجے کی خاطر قربانی کے لیے پیش کیا، اس سے ابوطالب کی ذاتی شرافت و نجابت پر ایک
نمایاں روشنی پڑتی ہے.دوسری طرف ابوطالب کی یہ قربانیاں اس بات کا بھی قطعی ثبوت
ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوئی میں مخلص خیال کرتا تھا.یقیناً ابو طالب ایک
خود غرض اور دھو کے باز انسان کے واسطے اس قدر قربانی کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا اور
اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو دیکھنے اور پڑتال کرنے کے لیے بھی
غیر معمولی مواقع حاصل تھے.“.ابوطالب کی وفات سے چند دن بعد حضرت خدیجہ نے بھی انتقال کیا.خدیجہ نے بڑی بڑی دکھ اور
،،
: زرقانی جلد ا صفحه ۲۹۵ ، ۲۹۶
۳ : لائف آف محمد صفحه ۱۰۳
: ابن سعد
: طبری وابن سعد
Page 210
۱۹۵
تکلیف کی گھڑیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور اُن کو آپ سے اور آپ کو ان سے
بہت محبت تھی.اس لیے طبعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کی وفات کا سخت صدمہ ہوا.وفات کے بعد
جب کبھی ان کا ذکر آتا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آتیں اور آپ اکثر اُن کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور
فرماتے تھے کہ خدیجہ اپنے زمانہ کی بہترین عورتوں میں سے تھی اور حضرت
عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ
حضرت خدیجہ کا اس کثرت سے ذکر خیر کیا کرتے تھے کہ مجھے اُن پر غیرت آنے لگتی تھی اور میں کہتی تھی کہ
آپ تو اس طرح خدیجہ کا ذکر فرماتے ہیں کہ گویا دنیا میں بس وہی ایک عورت پیدا ہوئی ہے.آپ
فرماتے تھے عائشہ ! اس میں بڑی بڑی خوبیاں تھیں اور خدا نے مجھے اولاد بھی اسی سے دی.غرض آر
ہمیشہ نہایت محبت کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے.اگر گھر میں کبھی کوئی جانور وغیرہ ذبح ہوتا تو
آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ضرور حصہ بھیجتے.ایک دفعہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف رکھتے
تھے کہ حضرت خدیجہ کی بہن ہالہ بنت خویلد آپ سے ملنے کے لیے آئیں اور دروازہ پر آ کر اجازت
چاہی.حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ بیتاب ہو کر اٹھے کہ خدیجہ کی سی آواز ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی
بہن ہالہ آئی ہے.جنگ بدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داما دابو العاص جو ابھی تک اسلام نہ
لائے تھے قید ہو کر آئے تو ان کی زوجہ یعنی آپ کی صاحبزادی زینب نے جو ابھی تک مکہ ہی میں تھیں.ان کے فدیہ کے طور پر اپنے گلے کا ہار اتار کر بھیجا.یہ وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے زینب کو جہیز میں دیا
تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس ہار کو دیکھا تو مرحومہ خدیجہ یاد آ گئی اور آپ کی آنکھیں ڈبڈبا
آئیں.صحابہ سے فرمایا: اگر چاہو تو خدیجہ کی یہ یاد گار اس کی بیٹی کو واپس کر دو.‘انہیں اشارہ کی دیر تھی
فوراً ہار واپس کر دیا..وفات کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر ۶۵ سال کی تھی.مکہ کے مقام حَجُون میں
دفن کی گئیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اُترے مگر نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی کیونکہ
ابھی تک جنازہ کی نماز مقرر نہ ہوئی تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف میں اضافہ حضرت خدیجہ اور ابوطالب کی وفات
کے بعد قریش مکہ آپ کی ذات کے
متعلق بہت دلیر ہو گئے اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکالیف پہنچانی شروع کیں.ل : بخاری باب تز و یج النبی صلعم خدیجه
: زرقانی
: ابن ہشام وطبری
: ابن ہشام وابن سعد
Page 211
۱۹۶
ایک دفعہ آپ ایک راستہ پر چلے جاتے تھے کہ ایک شریر نے برسر عام آپ کے سر پر خاک ڈال دی.ایسی
حالت میں آپ گھر تشریف لائے.آپ کی ایک صاحبزادی نے یہ دیکھا تو جلدی سے پانی لے کر آئیں
اور آپ کا سر دھویا اور زار زار رونے لگیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا.”بیٹی
رو نہیں.اللہ تیرے باپ کی خود حفاظت کرے گا اور یہ سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی یا پھر ایک دفعہ آپ
صحن کعبہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے سر بسجود تھے اور چند رؤساء قریش بھی وہاں مجلس لگائے بیٹھے تھے کہ
ابو جہل نے کہا.اس وقت کوئی شخص ہمت کرے تو کسی اونٹنی کا بچہ دان لا کر محمد کے اوپر ڈال دے.“
چنا نچہ عقبہ بن ابی معیط اُٹھا اور ایک ذبح شدہ اونٹنی کا بچہ دان لا کر جو خون اور گندی آلائش سے بھرا ہوا تھا
آپ کی پشت پر ڈال دیا اور پھر سب قہقہہ لگا کر ہننے لگے.فاطمتہ الزہرا کو اس کا علم ہوا تو وہ دوڑی آئیں
اور اپنے باپ کے کندھوں سے یہ بوجھ اتارا.تب جا کر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا.روایت آتی ہے کہ
ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رؤساء قریش کے نام لے لے کر جو اس طرح اسلام کو
ذلیل کرنے اور مٹانے کے درپے تھے بددعا کی اور خدا سے فیصلہ چاہا.راوی کہتا ہے کہ پھر میں نے دیکھا
کہ یہ سب لوگ بدر کے دن مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو کر داوی بدر کی ہوا کو متعفن کر رہے تھے.کے
حضرت عائشہ اور سودہ کی شادی نکاح کرنا اسلام میں ضروری قرار دیا گیا ہے اور سوائے
معذوری کی صورت کے تجرد سے روکا گیا ہے؛ چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :
النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلُ بِسُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى.یعنی شادی کرنا میری سنت میں داخل ہے اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے
نہیں ہے.“
اور خصوصاً ایک نبی اور شارع نبی کے واسطے تو شادی کرنا از بس ضروری ہے نہ صرف اس لیے کہ تا اس
ذریعہ سے وہ حسن معاشرت کا نمونہ اپنی اُمت کے واسطے قائم کر سکے بلکہ اس لیے بھی کہ تبلیغ احکام کے کام
میں اس کی بیوی اس کی مددگار ہو کیونکہ عورتوں کے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں اُن
کی تبلیغ و تعلیم جس خوبی
کے ساتھ ایک عورت کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتا بلکہ در حقیقت انبیاء کے واسطے تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر
کوئی مانع نہ ہو تو وہ حتی الوسع ایک سے زیادہ بیویاں کریں تا ان کے لیے تبلیغ و تعلیم کا کام اور بھی زیادہ
: طبری
بخاری حالات غزوہ بدر
ے : ابن ماجه
Page 212
۱۹۷
آسان ہو جاوے؛ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گذشتہ انبیاء علیہم السلام تعدد ازدواج کے مسئلہ پر کار بند
تھے.انبیائے بنی اسرائیل میں سے بھی کثرت ایسے ہی نبیوں کی تھی جن کی ایک سے زائد بیویاں تھیں یے
اور تعجب ہے کہ عیسائی لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اس مسئلہ کی وجہ سے اعتراض کرتے
ہیں مگر اپنے ان بزرگوں کی طرف نہیں دیکھتے جن کو وہ خدا کے مقرب اور برگزیدہ رسول یقین کرتے ہیں.اسی طرح دوسری قوموں کے بھی اکثر نبی تعدد ازدواج پر عامل تھے.غرضیکہ شادی کرنا بلکہ حتی الوسع ایک سے
زیادہ شادیاں کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے.لہذا حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے دل میں جلد ہی دوسری شادی کا خیال آنا آپ کے منصب نبوت کے لحاظ سے ایک طبعی امر تھا
مگر ایسے حالات میں ایک نبی کے واسطے بیوی کا انتخاب بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ کئی باتوں کو
دیکھنا اور کئی امور کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں کہ
وہ اس معاملہ میں آپ کا ہادی اور رہنما ہو.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سنا اور آپ کو ایک رؤیا کے
ذریعہ اپنے انتخاب سے اطلاع دی ؛ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ انہی ایام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک خواب دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے
ایک سبز رنگ کا ریشمی رومال پیش کر کے عرض کیا کہ 'یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں.آپ نے
رومال لے کر دیکھا تو اس پر حضرت عائشہ بنت ابو بکر کی تصویر تھی.اس کے کچھ عرصہ بعد خولہ بنت حکیم زوجہ عثمان بن مظعون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ
سے عرض کیا کہ 'یا رسول اللہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے ؟ آپ نے فرمایا.”رکس سے کروں؟“ اس
نے عرض کیا کہ آپ چاہیں تو کنواری لڑکی بھی موجود ہے اور بیوہ عورت بھی.آپ نے فرمایا.کون خولہ نے عرض کیا.کنواری تو آپ کے عزیز دوست ابو بکر صدیق کی لڑکی عائشہ ہے اور بیوہ سودہ
بنت زمعہ ہے جو آپ کے خادم سکران بن عمر و مرحوم کی بیوہ ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اچھا تو پھر تم ان دونوں کے متعلق بات کرو ؛ چنانچہ خولہ نے پہلے حضرت ابو بکر اور اُن کی اہلیہ اُتم رومان
سے ذکر کیا.وہ پہلے بہت حیران ہوئے اور کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
لے : مثلاً دیکھو حالات حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت موسی“ اور حضرت داؤد
اور حضرت سلیمان علیہم السلام
: مثلاً دیکھو حالات حضرت کرشن اور رامچند رجی وغیرہ ۳ : بخاری واسد الغابه
Page 213
۱۹۸
تو ہمارے بھائی ہیں.مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلا بھیجا کہ دین کی اخوت سے رشتہ پر اثر
نہیں پڑتا تو پھر انہیں کیا عذر ہو سکتا تھا بلکہ ان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی تھی کہ اُن کی بیٹی
رسول خدا کی بیوی بنے.اس کے بعد خولہ حضرت سودہ بنت زمعہ کے پاس گئیں.وہ اور ان کے عزیز بھی
راضی تھے.لہذا شوال ۱۰ نبوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ہر دو کے ساتھ چار چار سو درہم مہر پر
نکاح پڑھا گیا اور حضرت سودہ کا تو نکاح کے ساتھ ہی رُخصتانہ بھی ہو گیا لیکن چونکہ عائشہ کی عمر اس وقت
صرف سات سال
کی تھی اس لیے ان کا رخصتانہ ہجرت کے بعد تک ملتوی رہا ہے
اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے کہ جو جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں خدیجتہ الکبری کی وفات
سے خالی ہوئی تھی وہ دراصل حضرت عائشہ سے ہی پُر ہوئی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تجویز
حضرت عائشہ ہی کے متعلق تھی اور وہی آپ کو خواب میں بھی دکھائی گئی تھیں لیکن حضرت سودہ کا نکاح
ایک خاص مصلحت اور خاص ضرورت کے ماتحت تھا اور وہ یہ کہ چونکہ یہ زمانہ مسلمانوں کے واسطے ایک سخت
تکلیف اور مصیبت کا زمانہ تھا اور ظالم قریش کی طرف سے سب مسلمان مردوں ، عورتوں اور بچوں پر
جور و جفا کے تبر چل رہے تھے اور خصوصاً بے یارومددگار غرباء کے لیے تو یہ انتہائی مصائب کے دن تھے اس
لیے ایسی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ صدمہ خوردہ اور غم رسیدہ بیوہ بغیر کسی
انتظام کے چھوڑ دی جاوے اور اسلام کی وجہ سے مصیبت کے دن کاٹے اس لیے اور نیز اس لیے بھی کہ
آپ نے مسلمانوں کو آپس میں محبت رکھنے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور مدد کرنے کا عملی سبق بھی دینا
تھا.جب آپ کے سامنے سورہ کا ذکر آ گیا تو آپ نے بلا تامل یہی فیصلہ کیا کہ آپ انہیں خود اپنے
سایہ عاطفت میں لے لیں اور یہ آپ کی طرف سے ایک قربانی تھی جو حالات پیش آمدہ کے ماتحت کی گئی.کیونکہ اول تو سودہ ایک بیوہ تھیں.دوسرے وہ اچھی عمر رسیدہ تھیں.حتیٰ کہ شادی سے تھوڑے ہی عرصہ بعد
وہ مباشرت کے بالکل نا قابل ہو گئیں.تیسرے اُن میں آپ کی زوجیت کے واسطے کوئی امتیازی قابلیت
بھی یہ تھی اور نہ کوئی خاص وجہ کشش تھی.پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اُن کا آپ کے حرم میں آنا یہ معنے رکھتا تھا
کہ آپ اپنی اس بیوی پر ایک سوت لا رہے ہیں جو خدائی انتخاب کے ماتحت آپ کی زوجہ بنی تھی اور اس
لے : اس وقت تک صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا اخوت کا رشتہ سمجھتے تھے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ
رشتہ اخوت کا نہیں بلکہ امنیت اور ابوت کا ہے لیکن یہ کہ اس روحانی رشتہ کا اثر جسمانی رشتوں پر نہیں ہے.: زرقانی واسدالغابه
Page 214
۱۹۹
وجہ سے آپ کو بہت محبوب تھی اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اپنی محبوب بیوی پر کوئی شخص یونہی بلا خاص وجہ کے
سوت نہیں لا یا کرتا.پس حضرت عائشہ کے ہوتے ہوئے آپ کا حضرت سودہ جیسی عمر رسیدہ خاتون کے
ساتھ نکاح کرنا صاف بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی عیش وعشرت کا سامان نہ تھا جو آپ اپنے گھر لا رہے تھے
بلکہ یہ ایک قربانی تھی جو آپ کو حالات پیش آمدہ کے ماتحت کرنی پڑی تھی.پس آپ کی اصل اور مستقل تجویز حضرت عائشہ ہی کے لیے تھی جن کے متعلق خود اللہ تعالیٰ کی
طرف سے فیصلہ ہوا تھا اور وہی دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مناسب بھی تھیں کیونکہ:
اول :- وہ بالکل نو عمر لڑکی تھیں اور اس لیے پوری طرح اس قابل تھیں کہ اسلامی تعلیمات کو جلد،
بآسانی اور بخوبی سیکھ کر ایک دینی معلمہ بن سکیں جو ایک شارع نبی کی بیوی کے واسطے ضروری ہے.دوسرے :.وہ نہایت درجہ ذہین اور ذکی تھیں جس کی وجہ سے دینی مسائل کے سیکھنے اور تفقہ
فی الدین کے لیے نہایت مناسب تھیں.تیسرے:.بوجہ کم عمر ہونے کے ان کے متعلق بظاہر توقع تھی جو پوری بھی ہوئی کہ وہ ابھی بہت لمبی
عمر پائیں گی اور اس طرح انہیں مسلمان عورتوں میں تعلیم و تربیت اور تبلیغ کا زیادہ موقع مل سکے گا.چوتھے :- اسلام ہی میں اُن کی پیدائش ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسلامی تعلیم گویا اُن کی گھٹی میں
پڑی تھی اور بچپن سے ہی اُنہوں نے اسلامی عادات واطوار اچھی طرح سیکھ لیے تھے اور تعلیم اسلامی کا ایک
بہت عمدہ نمونہ تھیں.پانچویں:.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اوّل المومنین اور افضل المسلمین کی صاحبزادی
تھیں جس کی وجہ سے ان کی تربیت نہایت اعلیٰ اور کامل اور شعار اسلامی کے عین مطابق ہوئی تھی اور اس
لیے وہ عورتوں میں نمونہ بننے کے خاص طور پر قابل تھیں.ان وجوہات سے حضرت عائشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کے واسطے سب سے بڑھ کر
مناسب تھیں اور انہی وجوہ کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے ان کو پسند فرمایا؛ چنانچہ یہ باتیں اپنا پھل
لائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے وجود سے امت محمدیہ کو بڑے بڑے فائدے پہنچے ہیں.احادیث کا وہ حصہ جو عورتوں کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے زیادہ تر حضرت عائشہؓ ہی کے اقوال وروایات
پر مبنی ہے.پھر یہی نہیں بلکہ عام دینی مسائل میں بھی ان کو ایک خاص مرتبہ حاصل ہے؛ چنانچہ روایت
آتی ہے کہ:
Page 215
كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِعُونَ إِلَى قَوْلِهَا
يَسْتَفْتُونَهَا
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ بھی حضرت عائشہ کے قول کی
طرف رجوع کرتے اور ان سے فتویٰ پوچھتے تھے.“
غرض اصل اور مستقل تجویز آپ کی حضرت عائشہ سے تھی اور وہی اس منصب عالی کے لائق تھیں.باقی رہی حضرت سودہ بنت زمعہ کی شادی.سو جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں وہ ایک قربانی تھی جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیونکہ یہ شادی ایک خاص مر بیا نہ اصول کے ماتحت تھی جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی محبت اور قلبی توجہ اور حقیقی مہربانی کا ایک بین ثبوت ہے جو آپ ان مصائب کے
زمانہ میں اپنے خدام اور ان کے پسماندگان کے حال پر فرماتے تھے اور یہ بات حضرت سودہ کی ہی شادی
کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جیسا کہ آگے چل کر اپنے اپنے موقع پر ظاہر ہو جائے گا حضرت خدیجہ کی وفات
کے بعد حضرت عائشہ کے نکاح کے سوا جو کہ خود بالذات مقصود تھا باقی جتنے بھی نکاح آپ نے کیے وہ سب
خاص حالات، خاص ضروریات اور خاص مصالح کے ماتحت کئے گئے ؛ چنانچہ آپ کا خواب بھی یہی ظاہر کرتا
ہے جس میں آپ کو صرف حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی گئی تھی اور یہ الفاظ کہے گئے تھے کہ اب تیری یہ
بیوی ہے دنیا اور آخرت میں.اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے خاص محبت تھی.چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ سے دریافت کیا.ای النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ “ یعنی
یا رسول اللہ ! لوگوں میں سے آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ نے فرمایا: ” عائشہ سے.اس
،،
نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں سے کس سے زیادہ ہے؟ فرمایا: ابوھا.عائشہ کے باپ سے.“
حضرت عائشہ اور حضرت سودہ کا نکاح شوال ۱۰ نبوی میں ہوا تھا اور عام روایات کے مطابق حضرت
سودھ کے نکاح کی رسم حضرت عائشہ کے نکاح سے چند روز پہلے وقوع میں آئی تھی.اس وقت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال سے او پر تھی.تعدد ازدواج پر ایک مختصر نوٹ حضرت عائشہ اور حضرت سودہ کی شادی کے ذکر میں ہمارے
غیر مسلم ناظرین کے دل میں تعدد ازدواج کا مسئلہ ضرور کھٹکا
ہوگا.اس مسئلہ کے متعلق مفصل بحث تو انشاء اللہ کتاب کے حصہ دوم میں آئے گی مگر اس جگہ بھی ایک مختصر
زاد المعاد
: ترندی جلد ۲ باب فَضْلُ عَائِشَةَ
Page 216
۲۰۱
سا نوٹ لکھنا خالی از فائدہ نہ ہوگا.سو جاننا چاہیئے کہ اسلام کے کئی ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق مخالفین
نے یک طرفہ خیالات کے ماتحت اعتراض کر دیئے ہیں اور کبھی ٹھنڈے دل سے اُن پر غور نہیں کیا اور نہ
تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں ان کی حقیقت کو پرکھا ہے.انہی میں سے ایک تعد دازدواج کا مسئلہ ہے جس
کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے.سو اس بارہ میں پہلے تو یہ جاننا چاہیئے کہ فطرت بے شک
ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی ہدایت کے واسطے ودیعت کیا ہے لیکن یہ نور بعض
اوقات مخالف عناصر کے نیچے دب کر کمزور یا مُردہ بھی ہو جاتا ہے اور ایسے حالات میں اس کا فتویٰ قابل
قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو پھر تعصبات سے پاک نہ کیا جاوے؛ چنانچہ دیکھ لو مسئلہ طلاق کے متعلق
عیسائی فطرت صدیوں سے مخالف عناصر کے نیچے دب کر کمزور ہو گئی تھی اس لیے اس کا آج تک یہی فتویٰ
چلا آیا ہے کہ عورت کی طرف سے زنا سرزد ہونے کے سوا اسے طلاق دینا ہرگز جائز نہیں ہے؛ چنانچہ
اسی کے مطابق مسیحیوں نے اپنے قوانین بھی وضع کر لئے لیکن اب مشاہدہ اور تجربہ کے دھکے کھا کر ان کی
سوئی ہوئی فطرت کچھ بیدار ہوئی ہے اور وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ زنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں اور بھی ایسے
حالات ہو سکتے ہیں جن کے ماتحت میاں بیوی کا حسن معاشرت کے ساتھ اکٹھا رہنا محال ہو جاتا ہے.چنانچہ اب عیسائی ممالک میں اسلامی تعلیم کے مطابق طلاق کے متعلق قانون پاس ہورہے ہیں.بات یہ ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں اور دل اُن کی طرف پسندیدگی کا
میلان محسوس کرتا ہے مگر دراصل یہ ایک دھوکا ہوتا ہے کیونکہ عملی زندگی میں آکر ان کی حقیقت کا راز کھل
جاتا ہے.انہی میں سے مسئلہ طلاق ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے اور انہی میں سے تعد دازدواج کا
مسئلہ ہے جس کے متعلق یہ مختصر نوٹ سپر د قلم کیا جا رہا ہے.کہنے کو تو یہ ایک بڑی اچھی تعلیم ہے کہ انسان
ہر حالت میں ایک بیوی رکھے اور کسی حالت میں بھی اسے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا اختیار نہ ہونا چاہیے
لیکن اگر ہم غور سے کام لیں اور بنی نوع انسان کی مختلف ضروریات پر نظر ڈالیں تو ماننا پڑتا ہے کہ بعض
اوقات انسان پر ضرور ایسے حالات آتے ہیں کہ جب نہ صرف خود اس کی بلکہ سوسائٹی کی فلاح و بہبودی اس
بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں کرے.مثلاً (۱) کوئی ایسا شخص ہے جس کی ایک بیوی
موجود ہے مگر بیوی کے کسی نقص کی وجہ سے اُس سے اولاد نہیں ہوتی یا (۲) ہوتی تو ہے مگر ماں کے کسی نقص
کی وجہ سے مر مر جاتی ہے یا (۳) کوئی ایسا شخص ہے جس کی بیوی ایسے مرض میں مبتلا ہوگئی ہے کہ جس کی
وجہ سے وہ خاوند کی خاص ہمدردی اور توجہ کی تو ضرور حق دار ہے مگر وہ صحیح اہلی مباشرت کے قابل نہیں رہی یا
Page 217
۲۰۲
(۴) کوئی شخص بوجہ اپنے مخصوص حالات کے ایک بیوی کے ساتھ اپنے تقوی اور اخلاق کو قائم نہیں رکھ سکتا یا
(۵) کسی شخص کو دوسری شادی کے ساتھ کوئی اہم ملکی یا قومی مفاد وابستہ ہیں یا (۶) کسی زمانہ میں کسی ملک اور
قوم کی حالت اس بات کی مقتضی ہے کہ نسل کی ترقی یا قومی اخلاق کی حفاظت کے واسطے لوگ عام طور پر ایک
سے زیادہ شادیاں کریں یا (۷) دوسری شادی کے واسطے کوئی اور ایسی وجوہ ہیں جن کو عقل جائز قرار دیتی ہے تو
ایسے حالات میں ہر اک صحیح الدماغ شخص کا ضمیر بشرطیکہ وہ تعصبات کے نیچے دب کر مر نہ گیا ہو تعدد ازدواج کو
نہ صرف جائز بلکہ ضروری قرار دے گا اور اس قسم کے حالات میں مرد اور عورت دونوں سے توقع رکھی جائے گی
کہ وہ زیادہ اہم اغراض کے حصول کے لیے اپنے جذبات کی قربانی کرنے کے واسطے تیار ہو جائیں.اسلام ایک عملی مذہب ہے اور بنی نوع انسان کی تمام جائز ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور شکر کا
مقام ہے کہ صدیوں کی ٹھوکروں کے بعد اب عیسائی دنیا بھی آہستہ آہستہ اسلامی تعلیم کی طرف آ رہی ہے
اور وہ دن دور نہیں کہ دنیا جان لے گی کہ جو پاک اور کامل تعلیم تعصبات مذہبی وسیاسی کے سبب صدیوں سے
اعتراضات کا تختہ مشق بنی رہی ہے وہی اس قابل ہے کہ بنی نوع انسان کی تمام جائز ضروریات کو پورا
کر کے دنیا میں حقیقی امن کی بنیاد قائم کر سکے.افسوس معترضین نے بغیر سوچے سمجھے اسلامی مسئلہ تعدد ازدواج کے متعلق یہ خیال کر لیا ہے کہ
نعوذ باللہ یہ ایک عیش وعشرت کا راستہ ہے جو اسلام اپنے متبعین کے واسطے کھولتا ہے؛ حالانکہ اگر ان قیود کو
جن کے ساتھ اسلام نے تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے نظر غور سے دیکھا جاوے تو صاف پتہ لگ جاتا
ہے کہ ایک سچے مسلمان کے واسطے دوسری شادی ہرگز عیش و عشرت کا سامان نہیں ہو سکتی بلکہ سچ پوچھو تو یہ
ایک قربانی ہے جو اسے خاص حالات اور خاص ضروریات کے ماتحت کرنی پڑتی ہے اور اگر کوئی مسلمان اِن
قیود کو توڑ کر عیش وعشرت کی غرض سے ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو یہ اس کا ایک ذاتی فعل ہوگا جو کسی
صورت میں بھی اسلامی شعار نہیں کہلا سکتا.وہ ایک ایسا ہی کام کرتا ہے جیسا کہ بعض دوسرے مذاہب کے
آزاد طبع لوگ جن کا مذہب کسی صورت میں بھی تعدد ازدواج کی اجازت نہیں دیتا گھر میں ایک بیوی کے
ہوتے ہوئے ادھر اُدھر منہ کالا کرتے پھرتے ہیں.علاوہ ازیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیئے کہ اسلام میں
تعدد ازدواج کا حکم نہیں دیا گیا.یعنی یہ لازمی نہیں قرار دیا گیا کہ ہر مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں
کرے.بلکہ صرف یہ ایک استثنا ہے جو خاص حالات کے پیش آ جانے کی صورت میں جائز رکھی گئی ہے اور
عملاً بیشتر مسلمان ایک ہی شادی پر اکتفا کرتے ہیں.
Page 218
٢٠٣
توسیع اشاعت
قبائل کا دورہ حج کے ایام میں ہر دور دراز کے علاقہ سے مکہ میں لوگ جمع ہوتے تھے اور اشہر حرم میں
عکاظ.مجنہ اور ذوالمجاز میں بڑی بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا سے ہی یہ طریق تھا کہ ان موقعوں سے فائدہ اُٹھاتے تھے اور مختلف قبائل عرب کی
فرودگاہوں پر جا جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے یا مگر طبعاً اب تک آپ کی زیادہ توجہ قریش
مکہ کی طرف تھی لیکن جن ایام میں قریش مکہ نے مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں محصور کر کے ان کے
ساتھ تعلقات قطع کر دیے اور ان کے ساتھ میل ملاپ بند ہو گیا تو ان دنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے دیگر قبائل عرب کی طرف زیادہ توجہ شروع کی ؛ چنانچہ محصور ہونے کے زمانہ میں آپ آشہر حرم میں
جب کہ سب طرف امن ہوتا تھا حج میں آنے والے قبائل کا خاص طور پر دورہ کیا کرتے تھے اور عکاظ وغیرہ
کے اجتماعات میں بھی باقاعدہ جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے لیکن قریش مکہ نے اس تبلیغ میں بھی
روک تھام شروع کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قبائل کا مسلمان ہو جانا ان کے لیے قریباً قریباً ویسا ہی
خطرناک ہے جیسا کہ خود مکہ والوں کا اسلام لے آنا ؛ چنانچہ یہ قریش ہی کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ باوجود
اس کے کہ آپ نے کئی دفعہ قبائل کا دورہ کیا اور ہر کیمپ میں جا جا کر اسلام کی دعوت دی لیکن کہیں بھی
کامیابی کی امید نہ بندھی ہے
طائف کا سفر جب محاصرہ اٹھ گیا اور آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حرکات وسکنات میں ایک
گونه آزادی نصیب ہوئی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ طائف میں جا کر وہاں کے
لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں.طائف ایک مشہور مقام ہے جو مکہ سے جنوب مشرق کی طرف چالیس میل
کے فاصلے پر واقع ہے اور اس زمانہ میں قبیلہ بنو ثقیف سے آباد تھا.کعبہ کی خصوصیت کو الگ رکھ کر
طائف گویا مکہ کا ہم پلہ تھا اور اس میں بڑے بڑے صاحب اثر اور دولتمند لوگ آباد تھے اور طائف کی اس
ا : ابن سعد ذكر دعا رسول الله عله قبائل العرب في المواسم : ابن سعد وطبری
Page 219
۲۰۴
اہمیت کا خود مکہ والوں کو بھی اقرار تھا چنانچہ یہ مکہ والوں کا ہی قول ہے کہ :
لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمِ
د یعنی اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں
نازل نہ کیا گیا.“
غرض شوال ۱۰ نبوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف اکیلے تشریف لے گئے..یا بعض
روایتوں کی رو سے زید بن حارثہؓ بھی ساتھ تھے." وہاں پہنچ کر آپ نے دس دن قیام کیا اور شہر کے بہت
سے رؤساء سے یکے بعد دیگرے ملاقات کی ،مگر اس شہر کی قسمت میں بھی مکہ کی طرح اس وقت اسلام لانا
مقدر نہ تھا.چنانچہ سب نے انکار کیا بلکہ ہنسی اڑائی.آخر آپ نے طائف کے رئیس اعظم عبدیالیل کے
پاس جا کر اسلام کی دعوت دی مگر اس نے بھی صاف انکار کیا بلکہ تمسخر کے رنگ میں کہا کہ اگر آپ سچے
ہیں تو مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کی مجال نہیں اور اگر جھوٹے ہیں تو گفتگو لا حاصل ہے اور پھر اس خیال سے
کہ کہیں آپ کی باتوں کا شہر کے نوجوانوں پر اثر نہ ہو جائے ، آپ سے کہنے لگا بہتر ہوگا کہ آپ
یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہاں کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے.اس کے بعد اس
بد بخت نے شہر کے آوارہ آدمی آپ کے پیچھے لگا دیئے.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے تو یہ
لوگ شور کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لئے اور آپ پر پتھر برسانے شروع کئے جس سے آپ کا سارا
بدن خون سے تر بتر ہو گیا.برابر تین میل تک یہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور پتھر
برساتے چلے آئے.طائف سے تین میل کے فاصلہ پر مکہ کے رئیس عتبہ بن ربیعہ کا ایک باغ تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس میں آ کر پناہ لی اور ظالم لوگ تھک کر واپس لوٹ گئے.یہاں ایک سایہ میں کھڑے ہو کر آپ نے
اللہ کے حضور یوں دعا کی :
اللَّهُمَّ إِلَيْكَ اَشْكُرُ ضُعْفَ قُوَّتِي وَ قِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَا نِي عَلَى النَّاسِ
اللَّهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي - الخَ
یعنی ”اے میرے رب میں اپنے ضعف قوت اور قلت تدبیر اور لوگوں کے مقابلہ میں اپنی
ا : سورۃ زخرف : ۳۲
: ابن سعد
: ابن سعد
: ابن ہشام و طبری
۵ : حدیث میں ابن عبدیالیل کا نام آیا ہے.دیکھو بخاری کتاب بدء الخلق ذکر الملائکہ
Page 220
۲۰۵
بے بسی کی شکایت تیرے ہی پاس کرتا ہوں.اے میرے خدا تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا
ہے اور کمزوروں اور بیکسوں کا تو ہی نگہبان و محافظ ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے
میں تیرے ہی مُنہ کی روشنی میں پناہ کا خواستگار ہوتا ہوں کیونکہ تو ہی ہے جو ظلمتوں کو دور کرتا اور
انسان کو دنیا و آخرت کے حسنات کا وارث بناتا ہے.“
عتبہ وشیبہ اس وقت اپنے اس باغ میں موجود تھے.جب اُنہوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو
دور ونزدیک کی رشتہ داری یا قومی احساس یا نہ معلوم کس خیال سے اپنے عیسائی غلام عداس نامی کے ہاتھ
ایک کشتی میں کچھ انگور لگا کر آپ کے پاس بھجوائے.آپ نے لے لیے اور عداس سے مخاطب ہو کر فرمایا
کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اور کس مذہب کے پابند ؟“ اس نے کہا.”میں نینوا کا ہوں اور مذہباً
عیسائی ہوں.آپ نے فرمایا: ” کیا وہی نینوا جو خدا کے صالح بندے یونس بن متی کا مسکن تھا.عداس
نے کہا.ہاں.مگر آپ کو یونس کا حال کیسے معلوم ہوا ؟ آپ نے فرمایا.وہ میرا بھائی تھا کیونکہ وہ بھی
اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں.پھر آپ نے اُسے اسلام کی تبلیغ فرمائی جس کا اس پر بہت اثر ہوا
اور اس نے آگے بڑھ کر جوش اخلاص میں آپ کے ہاتھ چوم لیے.اس نظارہ کو دور سے کھڑے کھڑے
عتبہ اور شیبہ نے بھی دیکھ لیا؟ چنانچہ جب عداس ان کے پاس واپس گیا.تو انہوں نے کہا عد اس! یہ تجھے
کیا ہوا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ چومنے لگا.یہ شخص تو تیرے دین کو خراب کر دے گا حالانکہ تیرا دین اس
،،
کے دین سے بہتر ہے.تھوڑی دیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آرام فرمایا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور
نخلہ میں پہنچے جو مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے اور وہاں کچھ دن قیام کیا.اس کے بعد نخلہ سے
روانہ ہو کر آپ کوہ حرا پر آئے.اور چونکہ سفر طائف کی بظاہر نا کامی کی وجہ سے مکہ والوں کے زیادہ دلیر ہو
جانے کا اندیشہ تھا اس لیے یہاں سے آپ نے کسی شخص کی زبانی مطعم بن عدی
کو کہلا بھیجا کہ میں مکہ میں
داخل ہونا چاہتا ہوں ، کیا تم مجھے اس کام میں مدد دے سکتے ہو؟ مطعم پکا کا فر تھا مگر طبیعت میں شرافت تھی
اور ایسے حالات میں انکار کرنا شرفاء عرب کی فطرت کے خلاف تھا ، اس لیے اُس نے اپنے بیٹوں اور رشتہ
داروں
کو ساتھ لیا اور سب مسلح ہو کر کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور آپ کو کہلا بھیجا کہ آ جائیں.آپ
آئے اور کعبہ کا طواف کیا اور وہاں سے مطلعم اور اس کی اولاد کے ساتھ تلواروں کے سایہ میں اپنے گھر میں
ل : ابن ہشام وطبری
Page 221
۲۰۶
داخل ہو گئے.راستہ میں ابو جہل نے مطعم کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا.امجير ام تابع -
یعنی کیا تم نے محمد کو صرف پناہ دی ہے یا اس کے تابع ہو گئے ہو.“؟ مطعم نے کہا.”میں صرف پناہ
دینے والا ہوں تابع نہیں ہوں.“ اس پر ابو جہل نے کہا.”اچھا پھر کوئی حرج نہیں.‘ مطعم کفر کی
حالت میں ہی فوت ہوا مگر مسلمان ناقدر شناس نہیں تھے.حضرت حسان بن ثابت انصاری نے جو گویا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر تھے مطعم کے اس شریفانہ برتاؤ پر اس کی مدح میں زور دار
اشعار کہے جو ان کے دیوان میں اب تک محفوظ ہیں.طائف کا سفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا
ایک خاص واقعہ ہے.اس سفر کے حالات سے آپ کی ارفع شان اور بلند ہمتی اور بے نظیر صبر و استقلال کا
پتہ چلتا ہے؛ چنانچہ سرولیم میورلکھتا ہے:
محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) کے سفر طائف میں عظمت اور شجاعت کا رنگ نمایاں طور پر نظر
آتا ہے.ایک تنہا شخص جسے اُس کی قوم نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور رڈ کر دیا.وہ خدا کی
راہ میں دلیری کے ساتھ اپنے شہر سے نکلتا ہے اور جس طرح یونس بن متی نینوا کو گیا اسی طرح
وہ ایک بت پرست شہر میں جا کر اُن کو تو حید کی طرف بلاتا اور تو بہ کا وعظ کرتا ہے.اس واقعہ
سے یقینا اس بات پر بہت روشنی پڑتی ہے کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کو اپنے صدق دعویٰ پر
کس درجہ ایمان تھا.“
حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا
آپ کو کبھی جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا.عائشہ تیری قوم کی
طرف سے مجھے بڑی بڑی سخت گھڑیاں دیکھنی پڑی ہیں.پھر آپ نے سفر طائف کے حالات سنائے اور
فرمایا کہ اس سفر سے واپسی پر میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خدا نے آپ کے پاس
بھیجا ہے تا اگر ارشاد ہو تو میں یہ پہلو کے دونوں پہاڑ ان لوگوں پر پیوست کر کے ان کا خاتمہ کر دوں.“
آپ نے فرمایا.نہیں نہیں.مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا کر دے گا جو
66
خدائے واحد کی پرستش کریں گے.“
طائف کے سفر کے متعلق یہ بھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کا وفد
ل : بخاری کتاب بدء الخلق
روایت آئی ہے کہ جب آپ
Page 222
۲۰۷
*
اس سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو نخلہ میں رات کے وقت جب کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت
میں مصروف تھے جنات کا ایک گروہ جو سات نفوس پر مشتمل تھا اور شام کے ایک شہر نصیبین سے آیا تھا
آپ کے پاس سے گذرا اور اُس نے آپ کی تلاوت کو سنا اور اس سے متاثر ہوا اور جب یہ جن اپنی قوم کی
طرف واپس گئے تو اُنہوں نے اپنی قوم سے آپ کی بعثت اور قرآن شریف کا ذکر کیا.قرآن شریف میں
اس واقعہ کا دو جگہ ذکر آتا ہے اور دونوں جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنوں
کے آنے کا خود براہ راست علم نہیں ہوا بلکہ ان کے چلے جانے کے بعد خدائی وحی کے ذریعہ اس بات کی
اطلاع دی گئی کہ ایک جنوں کا گروہ آپ کی تلاوت کوسن گیا ہے.حدیث میں بھی متفرق جگہ اس واقعہ کا
ذکر آتا ہے اور گوتاریخی بیان سے حدیث کا بیان بعض تفصیلات میں مختلف ہے مگر مال ایک ہی ہے کہ
جنات کے ایک وفد نے ایک سفر کی حالت میں آپ کی تلاوت قرآن کریم کو سنا اور پھر اس سے متأثر
ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گیا.یہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے
روایات میں باہمی اختلاف ہو گیا ہے لیکن اس جگہ ہمیں اس واقعہ کی ظاہری تفصیلات سے زیادہ
سروکار نہیں ہے بلکہ مختصر طور پر صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس جگہ جنات سے کیا مراد ہے اور ان کا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلنا اور پھر کلام جید کی تلاوت سن کر واپس لوٹ جانا کس
غرض وغایت کے ماتحت تھا.سو جاننا چاہیے کہ جنوں کی ہستی کا عقیدہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کم و بیش دنیا کی ہر قوم میں پایا جاتا ہے
اور مذہبی اور غیر مذہبی ہر دو قسم کے لٹریچر میں اس کا وجود ملتا ہے مگر اس کی تفصیلات میں بہت اختلاف ہے
بعض قوموں کے لٹریچر میں جنات کے اندر ایک قسم کی خدائی طاقت تسلیم کی گئی ہے اور انہیں قابل پرستش مانا
جاتا ہے.بعض میں ان کو بلا استثنا ایک نا پاک مخلوق قرار دیا گیا ہے اور گویا شیطان اور ابلیس کی طرح
خیال کیا جاتا ہے مگر اسلام ان ہر دو قسم کے خیالات کو ر ڈ کرتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی ایک
مخفی مخلوق ہے جس میں انسانوں کی طرح اچھے اور بُرے دونوں قسم کے افراد پائے جاتے ہیں لیکن اس
مخلوق کا دائرہ انسانوں سے بالکل جدا ہے اور ایک علیحدہ عالم سے تعلق رکھتا ہے.البتہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ
کے منشاء کے ماتحت تمثیلی رنگ میں جنوں کے وجود کا خاص خاص انسانوں کو نظارہ کرا دیا جاتا ہے مگر ظاہر
زیادہ صحیح طور پر یہ شہر شام اور عراق کے درمیان واقع ہے.منہ
*
: سورۃ احقاف: ۳۰ و سورة جن: ۱
مثلا دیکھو صحیح مسلم کتاب الصلوۃ باب الحبر في الصبح
Page 223
۲۰۸
حالات میں یہ ہر دو مخلوق ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق اور واسطہ نہیں.قرآن شریف میں جنوں کا ذکر چھپیں مختلف مقامات پر آتا ہے.ان سب مقامات میں جن کے لفظ سے
ایک ہی معنے مراد نہیں ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے یہ لفظ عربی زبان میں مختلف معانی کے لیے
استعمال ہوتا ہے لیکن ان ۲۶ مقامات کے مجموعی مطالعہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جن خدا تعالیٰ
کی ایک مخفی مخلوق ہے جو انسانوں کی طرح ( گو اپنی تفصیلات میں یقینا اس سے بہت مختلف) ترقی اور تنزل
دونوں کا مادہ رکھتی ہے اور اپنے اعمال میں اچھے اور بُرے رستے کے اختیار کرنے کے لیے اپنی حدود مقررہ
کے اندراندر صاحب اختیار ہے مگر جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا ہے جن کا لفظ قرآن کریم میں ہر جگہ اس
مخفی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ بعض جگہ یہ لفظ غیر اصطلاحی معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے.در اصل جن ایک عربی لفظ ہے جس کے روٹ میں چھپنے یا چھپانے یا نظروں سے پوشیدہ ہونے یا
پردہ میں رہنے یا آڑ میں آجانے یا سایہ یا اندھیرا کرنے کے معنے ہیں.چنانچہ عربی میں جنت باغ کو کہتے
ہیں.کیونکہ اس کے درخت زمین پر سایہ کر کے اُسے چھپا لیتے ہیں.جنین اس بچہ کو کہتے ہیں جو ا بھی رحم مادر
میں ہے کیونکہ وہ رحم کے پردوں میں مخفی ہوتا ہے.مجنہ ڈھال کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ایک جنگجو
سپا ہی لڑائی کے وقت میں آڑلیتا ہے.جنون دیوانگی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے.جنان
دل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سینہ میں مخفی ہوتا ہے.اسی طرح جنان رات یا لباس کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اندھیرا
کرنے یا ڈھانکنے کا ذریعہ ہیں.جن قبر یا کفن کو کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں مردے کو اپنے اندر چھپا لیتے
ہیں.جان سانپ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ عمو مازمین کے مخفی سوراخوں میں زندگی گزارتا ہے.جنہ اوڑھنی کو
کہتے ہیں کیونکہ وہ سر اور چھاتی کو ڈھانکتی ہے وغیر ذالک.اس اصل کے ماتحت بعض اوقات عربی محاورہ
میں جن کا لفظ ایسے اُمراء ورؤساء کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے جو بوجہ امارت اور علو منزلت اور استکبار
کے عام لوگوں کی سوسائٹی میں میل جول نہیں رکھتے اور علیحدگی میں زندگی گزارتے ہیں ؛ چنانچہ بسا اوقات
-
۴۲ ،۱۵ ، ۱۳ :
-
سورة ذاریات : ۵۷ سورۃ انعام
۱۳۰ ، ۱۲۸ ، ۱۱۲ ، ۱۰۰ :
سورۃ کہف : ۵۱ - سورۃ نمل : ۱۸ ، ۴۰ سورۃ اعراف : ۳۹ ، ۱۸۰
ل : سورۃ سبا :
سورة رحمن : ۳۴
سورة فُصِّلَتْ يعنى حم سجده
۲۹ ، ۲۶ :
-
سورة احقاف : ۱۹ ، ۳۹
سورة بنی اسرائیل : ۸۹ سورة هود : ۱۲۰ سورة سجده : ۴
: اقرب الموارد
۱۴:
-
سورۃ جن : ۱ ، ۶
سورۃ الناس : ۷
Page 224
۲۰۹
قرآن شریف میں جن کا لفظ انس یعنی عامۃ الناس کے مقابلہ میں امراء کے طبقہ کے لئے استعمال ہوا
ہے اور ان معنوں میں یہ لفظ عمو ما بُرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.اسی طرح ایسی قوموں پر بھی جن کا
لفظ بول دیتے ہیں جو کسی ایسی علیحدہ اور منقطع جگہ میں آباد ہوں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا زیادہ
میل ملاپ ممکن نہ ہو اور انہی دو معنوں کے پیش نظر بعض محققین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں جنوں کے وفد کے حاضر ہونے سے یہ مراد لیا ہے کہ یہ لوگ یا تو خاص امراء کے طبقہ سے تعلق رکھتے
ہوں گے جنہوں نے بر ملا طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پر ہیز کیا اور
علیحدگی میں آپ کا کلام سن کر واپس چلے گئے اور یا وہ کسی دور افتادہ قوم کے افراد ہوں گے جو اپنے ماحول
کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے بالکل جدا اور علیحدہ رہتی ہوگی.ہمیں ان معنوں کے قبول کرنے میں
کوئی تامل نہیں ہے اور اگر نخلہ میں جنوں کے وفد کے حاضر ہونے سے مراد امراء کے کسی وفد کا حاضر ہونا
یا کسی دور افتادہ منقطع قوم کے افراد کا پیش ہونا مراد ہے تو پھر اس میں خدا تعالیٰ کا یہ اشارہ ہوگا کہ
اے رسول ! مکہ اور طائف میں بظاہر اپنی ناکامیوں کو دیکھ کر پریشان اور دلگیر نہ ہو کیونکہ اب وقت آتا ہے
کہ عوام الناس تو کیا بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ تیرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے اور دنیا کی دور افتادہ
قو میں تیری غلامی کا جوا اپنی گردنوں پر رکھیں گی.لیکن اگر جن سے وہ مخفی مخلوق مراد ہے جس کی تفصیلات کا ہم کو علم نہیں لیکن اس کا وجود نصوص قرآنی
کے ساتھ ثابت ہے تو اس میں بھی کسی عقلمند انسان کو شبہ کی گنجائش نہیں ہوسکتی کیونکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور
اس کی خلق کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ کسی مخلوق کی نظر اس کی انتہاء کو نہیں پاسکتی جہاں انسان کے سوا اس
مر کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں قسم کی دوسری مخلوق موجود ہے جن میں سے بعض قسم کی مخلوق مرئی
ہونے کے باوجود ہماری کوتاہ نظر سے پوشیدہ رہتی ہے اور اس مخلوق کے وجود پر علم طب اور سائنس کے
دوسرے شعبے یقینی قطعی شاہد ہیں تو پھر اس بات کے ماننے میں کیا تامل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق
جن کی قسم کی بھی موجود ہوگی جو باوجود انسانی نظر سے پوشیدہ ہونے کے اسی طرح زندہ اور قائم ہوگی جس
طرح انسان اپنے دائرہ کے اندر زندہ اور قائم ہے.بے شک اسلام ہمیں اس رنگ میں جنات کی تعلیم نہیں
دیتا کہ ہم موہومہ بھوتوں وغیرہ کی صورت میں کسی ایسی مخلوق کے قائل ہوں جس کے افراد انسانی نظروں
سے پوشیدہ رہتے ہوئے انسان کے لیے ایک تماشہ بنتے پھریں اور انسان کے سامنے مختلف صورتیں بدل
بدل کر اُس کی تفریح یا تخویف کا سامان بہم پہنچائیں.یہ خیالات جاہلانہ تو ہم پر مبنی ہیں.جن کا کوئی ثبوت
Page 225
۲۱۰
اسلامی تاریخ یا حدیث یا قرآن کریم میں نہیں ملتا مگر یہ کہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بیشمار دوسری
مخلوق ہے جس میں بڑی چھوٹی کثیف لطیف مرکی و غیر مرئی ہر قسم کی چیزیں شامل ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ
کی ایک مخلوق جن بھی ہے جو جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے، انسان کی نظروں سے مخفی ہے اور ایک
جدا گا نہ عالم سے تعلق رکھتی ہے اور عام حالات میں انسان کے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں.یہ وہ عقیدہ
ہے جس پر کوئی عقلمند اعتراض نہیں کرسکتا.باقی رہا یہ سوال کہ ان معنوں کی رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کے وفد
آنے سے کیا مراد ہے سو اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظارہ ایک کشفی نظارہ سمجھا جائے گا
اور اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس انتہائی درجہ پریشانی اور بے بسی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نظارہ
دکھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے رسول گودیسے ہر وقت ہی ہماری نصرت تیرے ساتھ ہے لیکن
جس طرح گرمی کی شدت خاص طور پر بادل کو پہنچتی ہے اسی طرح اب وقت آگیا ہے کہ ہماری مخفی طاقتیں
تیری رسالت کی تائید میں خصوصیت کے ساتھ مصروف کار ہو جائیں ؛ چنانچہ اس کے بعد جلد ہی حالات
نے پلٹا کھایا اور ہجرت میثرب کا پردہ اُٹھتے ہی خدا کی مخفی تجلیات اسلام کے جھنڈے کو اٹھا کر کہیں کا کہیں
لے گئیں اور روایات میں جو سات کا لفظ آتا ہے سو اس سے مخفی طاقتوں کا کامل ظہور مراد ہے کیونکہ عربی
میں سات کا عدد کمال کے اظہار کے لیے آتا ہے اور شام کے شہر نصیبین میں یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ
اسلامی فتوحات کی رو عرب کے بعد شام کے ملک سے شروع ہوگی.واللہ اعلم
قبیلہ دوس میں اسلام
ابتدائی ایام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوششوں کے علاوہ
اشاعت اسلام کا بڑا ذریعہ یہی تھا کہ کسی قبیلہ کا کوئی شخص اسلام لے آیا تو
پھر اس کے ذریعہ سے اس قبیلہ میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا.یا مسلمان مکہ سے نکل کر کہیں گئے تو اپنے
ساتھ اس نور کی شعاعوں کو بھی لیتے گئے.مثلاً قبیلہ بنو غفار میں ابوذر غفاری کے واسطے سے اور حبشہ میں
مہاجرین حبشہ کے ذریعہ سے اور یمن کے قبیلہ اشعر میں ابو موسیٰ اشعری کے مسلمان ہونے سے اسلام
داخل ہو چکا تھا.اب خدا کے فضل سے ایک اور قبیلہ میں بھی اس کا اثر پہنچ گیا اور وہ یوں ہوا کہ طفیل بن عمر و
قبیلہ دوس کا ایک معزز رئیس تھا اور شاعر بھی تھا.وہ کسی تقریب پر مکہ آنکلا.قریش نے اُسے دیکھا تو فکر
پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور مسلمان ہو جاوے.اس لیے وہ اس کے پاس گئے اور
اس سے کہا کہ " تم ہمارے شہر میں ایسی حالت میں آئے ہو کہ یہاں ایک شخص نے ہم میں سخت فتنہ
Page 226
۲۱۱
اور تفرقہ ڈال رکھا ہے.اس کی باتیں باپ کو بیٹے سے ، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتی
ہیں.ہمیں ڈر ہے کہ تم اس کی ساحرانہ باتیں سنو اور متاثر ہو جاؤ.لہذا ہم تمہیں بر وقت ہوشیار کرتے ہیں
کہ دیکھنا کہیں اس کی باتوں میں نہ آجانا.طفیل کہتے ہیں کہ مجھے قریش نے اس معاملہ میں اس طرح بار بار
تاکید کی کہ میں ان کی بات کو سچا سمجھ کر بہت خائف ہو گیا حتی کہ میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے
اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کان میں اچانک اس ساحر کی کوئی آواز پڑ جاوے
اور میں
کسی فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں.میں ایک دن اسی حالت میں صبح کے وقت مسجد حرام میں گیا تو وہاں میں
نے ایک کو نہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں.مجھے یہ نظارہ بھلا معلوم ہوا اور
میں آہستہ آہستہ آپ کے قریب چلا گیا.خدا کی قدرت باوجود یکہ میرے کان بند تھے پھر بھی کچھ کچھ آواز
مجھے سنائی دینے لگی اور میں نے دل میں کہا.”میری ماں مجھے کھوئے یا میں ایک سمجھدار شخص ہوں اور نیکی
بدی کی تمیز رکھتا ہوں.پس کیا حرج ہے کہ میں اس شخص کی بات سن لوں.اگر وہ اچھی ہوئی تو مان لوں گا
اور اگر بُری ہوئی تو انکار کر دوں گا.“ یہ خیال دل میں آنا تھا کہ میں نے کانوں سے روٹی نکال پھینکی اور
قرآن کی تلاوت سنتا رہا اور جب رسول اللہ نماز ختم کر چکے اور گھر کی طرف لوٹے تو میں ساتھ ہولیا اور
آپ سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی باتیں سنائیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلام الہی سنایا
اور توحید کی تبلیغ فرمائی.جس کا یہ اثر ہوا کہ میں وہیں مسلمان ہو گیا.پھر میں نے آپ سے عرض کیا.یا رسول اللہ ! میں اپنے قبیلے میں ممتاز حیثیت رکھتا ہوں اور لوگ میری بات مانتے ہیں.پس آپ دعا
کریں کہ میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی ہدایت دے.آپ نے اجازت دی اور دعا فرمائی.جب
طفیل اپنے قبیلہ میں پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد اور بیوی کو تبلیغ کی اور وہ مسلمان ہو گئے.پھر قبیلہ والوں کی طرف رُخ کیا اور ان کو اسلام کی طرف بلایا، مگر اُنہوں نے انکار کیا اور نہ مانا بلکہ
نفرت و مخالفت میں بڑھتے گئے.یہ حالت دیکھ کر طفیل پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوئے اور عرض کیا.یا رسول اللہ ! میری قوم نے تکذیب کی ہے اور مخالفت میں بڑھ گئی ہے.پس اب
آپ اُن کے واسطے بد دعا کریں.آپ نے ہاتھ اُٹھائے مگر بجائے بد دعا کرنے کے یہ الفاظ فرمائے کہ
اللَّهُمَّ اهْدِدَرْسًا “ یعنی ”اے میرے اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے.اور پھر آپ نے مجھ سے
لے : یعنی میں مروں.یہ ایک عربی کا محاورہ ہے جو کسی غلطی وغیرہ کے ارتکاب پر استعمال کیا جاتا ہے اور مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ
ایک ایسا کام ہے کہ اس سے مرنا بہتر ہے.منہ
Page 227
۲۱۲
فرمایا کہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے جاؤ اور نرمی اور محبت سے تبلیغ میں لگے رہو.طفیل کہتے ہیں کہ میں پھر
اپنے قبیلہ کی طرف واپس آیا اور ان میں تبلیغ کرتا رہا حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت
کی اور جنگ بدر اور اُحد اور احزاب ہو چکیں تب جا کر میری قوم نے اسلام قبول کیا.اس کے بعد میں اُن
میں سے ستر خاندانوں کے ساتھ مدینہ میں ہجرت کر آیا.یہ وہ زمانہ تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جنگ خیبر میں مصروف تھے یا حضرت ابو ہریرہ جو احادیث کے ایک مشہور راوی ہیں قبیلہ دوس سے تھے اور
انہی لوگوں میں مدینہ آئے تھے.طفیل بن عمرو روی کے متعلق یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں
کو قریش مکہ نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ ! آپ میرے پاس چل کر قیام فرما دیں.اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:
یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے.وہ جب ہجرت کا حکم دے گا، تبھی میرا نکلنا ہوگا اور پھر جہاں کا ارشاد
ہوگا وہیں جانا ہوگا.“
معراج اور اسراء معراج اور اسراء کے مسئلہ کو اسلامی لٹریچر میں جو پوزیشن حاصل ہے اور جو لمبی لمبی
بحثیں اس بارے میں کی گئی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں.یہ بخشیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد سے لے کر آج تک کے لٹریچر میں پائی جاتی ہیں مگر ہمیں
ایک مؤرخ ہونے کی حیثیت میں ان بحثوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں.ہمارے لیے صرف اس قدر
کافی ہے کہ معراج اور اسراء کے متعلق تاریخی لحاظ سے جو بات ثابت ہے اسے مختصر طور پر اپنے ناظرین
کے سامنے رکھ دیں مگر پیشتر اس کے کہ اصل واقعات بیان کیے جائیں بعض ان اصولی غلطیوں کا ذکر
ضروری ہے جو اس بحث میں عام طور پر واقع ہوئی ہیں جن میں بدقسمتی سے خود مسلمانوں کا ایک طبقہ
بھی مبتلا ہو گیا ہے.پہلی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے ایک حصہ نے اور ان کی پیروی میں بیشتر غیر مسلم مؤرخین نے
یہ سمجھ لیا ہے کہ معراج اور اسراء ایک ہی واقعہ کے دو مختلف نام ہیں یا کم از کم یہ کہ وہ ایک ہی واقعہ کے
دو مختلف حصوں کے نام ہیں حالانکہ قرآن شریف اور صحیح احادیث اور مستند تاریخی روایات کے مطالعہ سے
جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دراصل معراج اور اسراء دو مختلف چیزیں ہیں جو خواہ ایک دوسرے کے
ل : ابن ہشام واسد الغابه
Page 228
۲۱۳
قریب قریب واقع ہوئی ہوں اور خواہ ان کا آپس میں روحانی رنگ میں کوئی جوڑ اور رابطہ بھی ہو مگر حقیقہ وہ
ایک دوسرے سے جدا اور مختلف ہیں یعنی معراج تو اس روحانی سفر کا نام ہے جس میں آپ کو مکہ سے اُٹھا
کر آسمان تک پہنچایا گیا جہاں بالآخر آپ خداوند عالمیان کے دربار میں پیش ہوئے اور اسراء ایک دوسرا
سفر ہے جو آپ کو بعض مصالح کے ماتحت مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کرایا گیا.قرآن شریف نے
ان ہر دوسفروں کو علیحدہ علیحدہ سورتوں میں علیحدہ علیحدہ کیفیات اور تفاصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ؛ چنانچہ
سورۃ نجم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روحانی پرواز کا ذکر آتا ہے وہ معراج ہے.جیسا کہ
بخاری میں بھی سورۃ نجم کی آیات کو معراج کے واقعہ پر چسپاں کر کے اشارہ کیا گیا ہے اور سورۃ بنی اسرائیل
میں سے جس سفر کا ذکر ہے وہ اسراء ہے اور ان دونوں کی تفصیلات اور کیفیات ایک دوسرے سے بالکل جدا
ہیں.مثلاً سورۃ بنی اسرائیل میں اسراء کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن شریف نے آسمان کا ذکر تک
نہیں کیا اور سورۃ نجم کے بیان میں بیت المقدس کا کوئی ذکر نہیں آتا.اسی طرح احادیث کے بغور مطالعہ سے بھی معراج اور اسراء کا جدا جدا ہونا ثابت ہوتا ہے چنانچہ
بخاری میں جو قرآن شریف کے بعد اسلامی لٹریچر میں صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے.اسراء اور معراج کے
علیحدہ علیحدہ باب باندھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں.اور دونوں
سفروں کی جدا جدا ابتداء بیان کرنے میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ ہر دوسفر ایک
دوسرے سے جدا تھے.یعنی جہاں اسراء کے متعلق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ
سے لے کر بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی وہاں معراج کے متعلق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ کو مکہ سے
آسمان کی طرف اُٹھایا گیا.گویا ہر دوسفروں کی ابتداء علیحدہ علیحدہ طور پر مکہ سے ہی ہوئی جس سے ان کا
ایک دوسرے سے جدا اور متغائر ہونا ظاہر وعیاں ہے.علاوہ ازیں باوجود اس کے کہ معراج کی حدیث
بخاری میں چھ مختلف جگہوں میں بیان ہوئی ہے اور اسی طرح اسراء کی حدیث بھی متعدد جگہ آئی ہے اور بعض
جگہ راویوں کی بے احتیاطی سے جزوی طور پر اسراء اور معراج کے بیان میں کسی قدر خلط بھی ہو گیا ہے لیکن
کہیں بھی معراج کے بیان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف جانا مذکور نہیں ہوا بلکہ
ل : النجم : ۸ تا ۱۰
ے
: بنی اسرائیل : ۲
: دیکھو بخاری ابواب الاسراء والمعراج
: بخاری کتاب التوحید باب قَوْلِهِ وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً
: دیکھو بخاری ابواب الاسراء والمعراج
Page 229
۲۱۴
ساری کی ساری روایات میں مکہ سے سیدھا آسمان کی طرف اُٹھایا جانا بیان کیا گیا ہے.جس سے معراج
کا اسراء سے جدا ہونا یقینی طور پر ثابت ہے.اسی طرح سیرت ابن ہشام میں جو سیرۃ کی کتابوں میں سب
سے زیادہ متداول کتاب ہے.معراج اور اسراء کو بالکل علیحدہ علیحدہ طور پر بیان کیا گیا ہے اور یہ تصریح ہے
کہ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس تشریف لے
آئے تھے اور معراج کا واقعہ علیحدہ طور پر ہوا تھا.اسی طرح مشہور مؤرخ ابن سعد نے بھی معراج اور اسراء
کو علیحدہ علیحدہ تاریخوں میں علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے.ان شہادتوں سے یہ بات قطعی
طور پر ثابت ہوتی ہے کہ خواہ معراج اور اسراء کا روحانی طور پر آپس میں کوئی تعلق اور رابطہ ہو مگر واقعہ
کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متفائر چیزیں تھیں جو جدا جدا طور پر علیحدہ علیحدہ
کوائف کے ساتھ وقوع پذیر ہوئیں؛ چنانچہ متقدمین میں سے بھی ایک معتد بہ حصہ نے معراج اور اسراء
کو علیحدہ علیحدہ قرار دیا ہے.دوسری غلطی اس بحث میں یہ ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سفروں کو ظاہری سفر قرار
دے دیا گیا ہے جو گویا اس مادی جسم کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے؛ حالانکہ مذکورہ بالا تینوں شہادتیں اس خیال
کو بھی سختی سے رڈ کرتی ہیں؛ چنانچہ قرآن شریف میں معراج کے متعلق جو بیان آتا ہے.اس میں یہ الفاظ
آتے ہیں کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأی یعنی اس موقع پر جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل
نے دیکھا وہ بالکل ٹھیک ٹھیک اور سچ تھا اور آپ کے قلب صافی نے اس نظارہ کے دیکھنے اور سمجھنے میں کوئی
غلطی نہیں کی.اس سے صاف ثابت ہے کہ یہ ایک قلبی نظارہ تھا نہ کہ ایک جسمانی اور مادی سفر.اسی طرح
حدیث میں بھی یہ واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ معراج ایک روحانی امر تھا.چنانچہ حدیث میں یہ الفاظ آتے
ہیں کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اُٹھائے جانے کا نظارہ دکھایا گیا.اس وقت آپ
سور ہے تھے مگر یہ کہ آپ کا یہ سونا عام لوگوں کی طرح کا سونا نہ تھا بلکہ اس خاص شان نبوت سے تعلق رکھتا تھا
ل : دیکھو بخاری کتاب الصلوۃ باب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلوة وكتاب بدء الخلق بابت ذکر الملائکہ وہاب ادریس علیہ السلام و
باب كَانَ النَّبِيُّ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَ باب المعراج و كتاب التوحيد باب قوله كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا.ے : سیرۃ ابن ہشام ذکر الاسراء
: طبقات ابن سعد جلدا ۴: دیکھو زرقانی بحث اسراء ومعراج جلدا وجلد ۶ میں ذکر اسراء و معراج و سیرت حلبیہ
ذکر معراج
۵ : سورة نجم : -
۱۲ :
Page 230
۲۱۵
جس میں آپ کی آنکھ تو سوتی تھی مگر دل بیدار رہتا تھا.اور ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ
معراج کا نظارہ آپ کو نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں دکھایا گیا.اور ایک تیسری روایت میں یہ
مذکور ہے کہ معراج کے نظارہ کے بعد آپ بیدار ہو گئے.اور ایک چوتھی روایت میں حضرت عائشہ
فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے یہ کہے کہ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جسمانی
آنکھوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے.اس کی بات ہرگز نہ مانو اور فرماتی ہیں کہ میرے تو
اس خیال سے ہی بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ آپ نے ان جسمانی آنکھوں سے خدا تعالیٰ
کو دیکھا تھا.پھر کتب سیرۃ میں بھی ایسی روایات کی کمی نہیں ہے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معراج ایک
روحانی امر تھا نہ کہ ظاہری اور جسمانی سفر.چنانچہ مشہور اسلامی مورخ ابن اسحاق نے حضرت عائشہ سے
یہ روایت نقل کی ہے کہ مَا فُقِدَ جَسَدُهُ یعنی معراج کی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک
غائب نہیں ہوا بلکہ تمام وقت اسی مادی دنیا میں موجود رہا.اس سے بڑھ کر معراج کے روحانی ہونے
کے متعلق کیا شہادت ہوگی ؟
اسی طرح اسراء کے متعلق قرآن شریف اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ وہ ایک روحانی امر تھا
جو خاص مصالح کے ماتحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا؛ چنانچہ قرآن شریف نے اس کے متعلق
تین باتیں بیان کی ہیں.اول یہ کہ سفر رات کے وقت ہوا جیسا کہ اسرای کے لفظ میں اشارہ کیا گیا ہے.دوم یہ کہ وہ ایک ہی رات کے دوران میں مکمل ہو کر ختم ہو گیا جیسا کہ کیلا کے لفظ سے پایا جاتا ہے اور
سوم یہ کہ اس سفر کی غرض و غایت یہ تھی کہ ہم اپنے رسول کو اپنے بعض نشانات دکھا ئیں.اب جب ہم غور
کرتے ہیں تو یہ تینوں باتیں اسراء کو ایک روحانی سیر ثابت کرتی ہیں نہ کہ ایک ظاہری اور جسمانی سفر.کیونکہ اول تو عام حالات میں ظاہری سفر کا وقت دن ہے اور رات کے وقت سفر کرنا ایک استثنائی صورت
رکھتا ہے اور اس کے مقابل پر روحانی سیر یعنی رؤیا وغیرہ کے لئے اصل وقت رات ہے اور دن کے وقت
اس کا واقع ہونا ایک گونہ استثنائی رنگ رکھتا ہے.پس اللہ تعالیٰ نے رات کا لفظ استعمال کر کے یہ اشارہ
فرمایا ہے کہ یہ ایک روحانی سفر تھا جو بصورت رؤیا وقوع پذیر ہوا.ورنہ رات کے ذکر میں کوئی خاص حکمت
لے : بخاری ابواب صفة التي باب تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ : بخاری ابواب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ
: بخاری کتاب التوحید باب قَوْله وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيمًا ۴ : بخاری کتاب التفسیر باب تفسیر سورۃ نجم
۵ : ابن ہشام ذکر الاسراء
1 : سورۃ بنی اسرائیل : ۲
Page 231
۲۱۶
نظر نہیں آتی.دوسرے اس سفر کے متعلق ان الفاظ کا استعمال کیا جانا کہ وہ ایک رات کے دوران میں مکمل
ہو کر ختم ہو گیا سوائے اس کے اور کسی غرض و غایت کے لیے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے روحانی ہونے کی
طرف اشارہ کیا جائے.کیونکہ عام حالات میں مادی اسباب کے ماتحت مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا
سفر ایک رات کے اندراندر پورا ہونا بالکل ممکن نہ تھا.تیسرے اس سفر کی غرض وغایت کے متعلق جو یہ بیان
کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو یہ سفر اس لیے کرایا ہے کہ اُسے اپنے بعض نشانات دکھائیں، یہ بھی
اسے ایک روحانی امر ثابت کرتا ہے کیونکہ مکہ سے لے کر بیت المقدس کا ظاہری اور جسمانی سفر خواہ وہ
ایک رات کے قلیل عرصہ میں ہی تکمیل کو پہنچ جائے ایک عجوبہ نمائی کے سوا اپنے اندر کوئی خاص شان کا پہلو
نہیں رکھتا جسے مقام نبوت کے مناسب حال سمجھا جا سکے؛ البتہ اگر اس سفر کو کشفی رنگ میں ایک روحانی امر
سمجھا جائے جس سے تصویری زبان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی آئندہ ترقیات اور
فتوحات مراد ہوں تو تب بیشک وہ ایک مقتدرانہ پیشگوئی کی صورت میں ایک بہت بڑا نشان قرار پاتا ہے
جس کے مقابل پر ظاہری سفر کو کچھ بھی حیثیت حاصل نہیں.علاوہ ازیں قرآن شریف نے اسی سورۃ
بنی اسرائیل میں جس کے ابتداء میں اسراء کا ذکر آتا ہے، اسراء کے متعلق رؤیا کا لفظ استعمال کیا ہے.جس سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ سفر ایک رؤیا کے رنگ میں تھا نہ کہ ایک ظاہری اور جسمانی
سفر.مگر اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ عربی میں رویا کے معنے صرف خواب کے نہیں ہوتے بلکہ عربی
محاورہ کے مطابق رویا کا لفظ ہر اس روحانی نظارہ پر بولا جاتا ہے جو کسی انسان کو بطریق خواب یا کشف
وغیرہ دکھایا جائے اور ہر قسم کے روحانی مناظر اس کے اندر شامل ہیں.پس جہاں اسراء یا معراج کے
متعلق رؤیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہاں اس سے اردو محاورہ کے مطابق خواب مراد نہیں ہوتی بلکہ ایک
اعلی درجہ کا روحانی کشف مراد ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ارفع اور اعلیٰ شان کے
مطابق خاص مصالح الہی کے ماتحت دکھایا گیا.بہر حال قرآن شریف نے واضح ارشادات کے ذریعہ
اس بات کو کھول کر جتا دیا ہے کہ اسراء کوئی مادی امر نہیں تھا بلکہ وہ روحانی سفر تھا جس کی غرض و غایت
خدا کے بعض مقتدرانہ نشانات دکھانا ہی تھی.اسی طرح حدیث میں بھی اسراء کے متعلق صاف اشارہ آتا ہے کہ وہ ایک روحانی امر تھا نہ کہ جسمانی
اور ظاہری سفر.چنانچہ روایت آتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے
له : سورۃ بنی اسرائیل :
۶۱ :
Page 232
۲۱۷
اللہ تعالیٰ نے مکہ کی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس کی مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی تو اس پر کفار مکہ نے
جن میں سے بعض بیت المقدس کو دیکھ چکے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی
بیت المقدس نہیں گئے.یہ اعتراض کیا کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ درست ہے تو آپ بیت المقدس کا کوئی نظارہ
بیان کریں.اس پر آنحضرت کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی کیونکہ گو آپ رؤیا میں بیت المقدس کو دیکھ
چکے تھے مگر آپ جانتے تھے کہ یہ ایک رؤیا کا معاملہ ہے جس میں ممکن ہے کہ آپ کے ذہن کا نقشہ ظاہر کے
ساتھ بالکل مطابقت نہ کھاتا ہو اور آپ کو رڈیا کے مخصوص مناظر کے سوا بیت المقدس کے عام مناظر کا علم
بھی نہیں تھا اس لیے طبعاً آپ کو کفار کے اس اعتراض پر لوگوں کی ٹھوکر کے خیال سے فکر پیدا ہوا مگر
اللہ تعالیٰ نے فوراً کشفی رنگ میں بیت المقدس کا ظاہری نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کیا اور
آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے ہوئے کفار کو بتایا کہ بیت المقدس کی یہ یہ نشانیاں ہیں.اس پر
کفار شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئے.اب اگر اسراء اس ظاہری جسم کے ساتھ ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم بیت المقدس کے مناظر کو واقعی اپنی ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ ملا حظہ فرما چکے تھے.تو کفار کے
اعتراض پر آپ کو فکرمند ہونے اور اللہ تعالیٰ کو بیت المقدس کا دوبارہ نظارہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟
کفار کے اعتراض پر آپ کا فکرمند ہونا اور خدا تعالیٰ کا دوبارہ نظارہ دکھا نا صاف ظاہر کرتا ہے کہ دراصل
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل بیت المقدس کو حقیقی طور پر نہیں دیکھا تھا اور صرف اعتراض
ہونے پر اس کا حقیقی نظارہ دکھایا گیا اور پہلا نظارہ جو اسراء کے موقع پر ہوا تھا، اس میں بیت المقدس کا
نقشہ صرف عالم رؤیا کا ایک اجمالی نقشہ تھا جس کی بنا پر آپ اس بستی کی تفصیلات نہیں بتا سکتے تھے.الغرض قرآن شریف اور احادیث اور تاریخ تینوں سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ معراج اور
اسراء خالصۂ روحانی امور تھے جو بعض خاص مصالح کے ماتحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے
اور جن لوگوں نے اس کے خلاف ادعا کیا ہے ان کے ہاتھ میں سوائے کمزور اور بودے استدلالات کے
اور کچھ نہیں.ہاں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں ہماری مراد معراج اور اسراء کے روحانی ہونے سے ہرگز
یہ نہیں ہے کہ یہ نظارے معمولی خواب کے نظارے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں
دکھائے گئے.جو شخص یہ خیال کرتا ہے اس نے اسراء اور معراج کی حقیقت کو ہرگز نہیں سمجھا اور یقیناً وہ ان
لوگوں سے بڑھ کر غلطی خوردہ ہے جو ان مناظر کو جسمانی اور ظاہری حالت کے ساتھ وابستہ قرار دیتے ہیں
لے: دیکھو بخاری تفسیرسورۃ بنی اسرائیل آیت اسراء ومسلم باب فی ذکر مسیح ابن مریم تفسیر ابن کثیر آیت اسراء
Page 233
۲۱۸
بلکہ حق یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص کے روحانی مقام کے لحاظ سے اس کے روحانی قومی تیز اور لطیف ہوتے چلے
جاتے ہیں اور اس کے مقابل پر اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے لیے اُن کے مقام قرب کے
لحاظ سے روحانی بلندیوں کے دروازے کھولتا ہے.اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روحانی
مناظر آپ کے ارفع و اعلیٰ مقام کے لحاظ سے دوسروں کے لطیف ترین کشوف سے بھی آگے نکلے ہوئے تھے
جن میں آپ کو ایک سراسر نورانی جسم کے ساتھ ان بلند ترین روحانی چوٹیوں کی سیر کرائی گئی جہاں
آج تک کسی بشر کا قدم نہیں پہنچا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابل پر محض ایک خواب کو کچھ بھی حیثیت
حاصل نہیں اور نہ ہی اس کے سامنے محض ایک ظاہری اور جسمانی پرواز کو جو ایک عجوبہ نمائی سے بڑھ کر
نہیں کوئی حقیقت حاصل ہے.ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کسی بشر کو اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر لے جانے کی
قدرت نہیں رکھتا بلکہ غرض صرف یہ ہے کہ قرآن شریف اور صحیح احادیث اور مستند تاریخی روایات سے یہ
بات ثابت نہیں ہوتی کہ اسراء یا معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جسم عنصری کے ساتھ اٹھائے
گئے ہوں بلکہ اس کے برعکس جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک نہایت لطیف اور پاکیزہ قسم کی
روحانی پرواز تھی جو بطریق رویا آپ کو کرائی گئی اور تصویری اور تعبیری زبان میں اس پرواز کے اندر بہت
سے حقائق اور اشارات مخفی تھے جو ایک عظیم الشان نشان کے طور پر اپنے وقت پر پورے ہوئے اور ہور ہے
ہیں.دوسری طرف اس جگہ اس بات کے بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ گو خدائی قدرت کے لحاظ
سے سبھی کچھ ممکن ہے مگر خدا تعالیٰ نے بعض امور کو خود اپنی سنت کے خلاف قرار دیدیا ہے اور انہی میں کسی
بشر کا اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھایا جانا ہے.چنانچہ قرآن شریف میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر
آتا ہے کہ جب ایک موقع پر کفار مکہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ ہمیں
آسمان پر چڑھ کر دکھلاویں تو آپ نے انہیں خدائی منشا کے ماتحت یہ جواب دیا کہ سُبْحَانَ اللہ ! میں تو
صرف ایک انسان رسول ہوں اور ایک انسان رسول کا اس طرح آسمان پر جانا خدائی سنت کے خلاف ہے
اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ یہ واقعہ قرآن شریف نے اسی سورۃ میں بیان فرمایا ہے جس میں اسراء کا ذکر
آتا ہے.اسی طرح بعض دوسری آیات میں بھی یہ صاف مذکور ہے کہ ایک انسان اس دنیوی زندگی میں
عالم مادی کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا.لے : دیکھوسورۃ بنی اسرائیل :
۹۴ :
: انعام : ۳۶ و المرسلات : ۲۷،۲۶
Page 234
۲۱۹
اسراء اور معراج کے بارے میں دو اصولی غلطیوں کے ازالہ کے بعد ہم اصل واقعہ کو لیتے ہیں یعنی یہ
کہ ان کشوف کی تفصیلات کیا تھیں.وہ کس جہت سے آیات الہی کے حامل تھے اور وہ کب وقوع پذیر
ہوئے.پہلے ہم معراج کو لیتے ہیں.سو جاننا چاہیئے کہ معراج ایک عربی لفظ ہے جو عرج سے نکلا ہے جس
کے معنے اوپر چڑھنے کے ہیں.چنانچہ اسی وجہ سے عربی میں معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں جو گویا اوپر چڑھنے
کا آلہ اور واسطہ ہے.معراج کی تفصیل قرآن شریف میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ:
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُومِرَّةٍ فَاسْتَوى ( وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى
أَفَتُمُرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْرَاهُ نَزْلَةً أُخْرى ، عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا
جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَخْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى
مِنْ أَيْتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى
یعنی خدا نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خود تعلیم دی ہے.وہی خدا جو بڑی طاقتوں کا
مالک اور صاحب قوت وسطوت ہے سو ( اس تعلیم کے نتیجہ میں ) یہ رسول ایستادہ ہو کر بلند ہوا
حتی کہ وہ بلند ہوتا ہوتا افق اعلیٰ تک جا پہنچا.پھر وہ خدا سے قریب ہوا اور خدا بھی اس کی طرف
جھ کا حتی کہ وہ دونوں یوں ہو گئے جیسے دو کمانوں کے ملنے سے اُن کا چلہ ایک ہو جاتا ہے (یعنی
کما نہیں تو الگ الگ رہتی ہیں مگر تیر چلانے کی جگہ ایک ہو جاتی ہے اور مقصد و مرمی کے لحاظ
سے کوئی دوئی نہیں رہتی ) اس حالت میں خدا نے اپنے اس رسول کو وہ وحی کی جو اُ سے کرنا تھی اور
رسول کے قلب صافی نے اس نظارہ کے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی بلکہ جو کچھ دیکھا ٹھیک ٹھیک
دیکھا.کیا اے لوگو تم ہمارے رسول کے اِن روحانی مناظر کو شک کی نظر سے دیکھتے ہو؟ حالانکہ
اس نے تو اس وقت (اس سے بھی بڑھ کر ) ایک اور نظارہ بھی دیکھا تھا.وہی جو اُس نے اس
انتہائی بیری کے قریب دیکھا.وہ بیری جو ابدی رہائش والی جنت کے پاس ہے جبکہ اس بیری پر
ایک خاص تجلی کا ظہور ہو رہا تھا.یقیناً اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ غلط راستہ پر نہیں
پڑی اور نہ ہی وہ حد مقررہ سے آگے نکلی اور آپ نے اس نظارہ میں خدائے ذوالجلال کے
بڑے بڑے نشان ملاحظہ کئے.“
"
لے : سورة نجم : ۶ تا ۱۹
Page 235
۲۲۰
اس قرآنی بیان کی تشریح، تفصیل میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اُن میں بدقسمتی سے کسی قدر اختلاف
پایا جاتا ہے اور جیسا کہ قاعدہ ہے جوں جوں کوئی روایت اعتبار کے اعلیٰ مقام سے نیچے گرتی گئی ہے توں
توں اس میں کمزور حصہ کا دخل زیادہ ہوتا گیا ہے.اس لیے ہم اس جگہ صرف مضبوط اور معتبر روایتوں تک
اپنے آپ کو محدود رکھیں گے.اور اُن میں سے بھی صرف اس حصہ پر اکتفا کریں گے جو ہماری تحقیق میں
اختلاف و اختلاط سے پاک ہے.سو جانا چاہیئے کہ معراج کے متعلق صحیح روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ:
ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اس حصہ میں جو حطیم کہلاتا ہے لیٹے ہوئے تھے اور
یقظه اور نوم کی درمیانی حالت تھی.یعنی آپ کی آنکھ تو سوتی تھی مگر دل بیدار تھا کہ آپ نے دیکھا کہ
جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے ہیں.حضرت جبرائیل نے آپ کے قریب آ کر آپ کو اٹھایا اور چاہ زمزم
کے پاس لا کر آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو زمزم کے مصفا پانی سے اچھی طرح دھویا.اس کے
بعد ایک سونے کی طشتری لائی گئی جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی اور حضرت جبرائیل نے آپ کے دل
میں حکمت و ایمان کا خزانہ بھر کر آپ کے سینہ کو پھر اُسی طرح بند کر دیا.اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام
آپ کو اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف اُٹھ گئے اور پہلے آسمان کے دروازہ پر پہنچ کر دستک دی.دربان نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں.دربان نے پوچھا.کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا.ہاں.اس پر دربان نے
دروازہ کھول کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا.اندر داخل ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بزرگ انسان کو دیکھا.جس نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا.” مرحبا اے صالح نبی اور اے صالح
فرزند.اور آپ نے بھی اُسے سلام کیا.اس شخص کے دائیں اور بائیں ایک بہت بڑی تعداد میں روحوں کا
سایہ پڑ رہا تھا.جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا تھا اور جب بائیں
طرف دیکھتا تھا تو غم سے اس کا منہ اُتر جاتا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا! یہ
صاحب کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ آدم ہیں اور ان کے دائیں طرف ان کی نسل میں سے اہل جنت کا
سایہ پڑ رہا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف اہل نار کا سایہ ہے جسے دیکھ کر وہ غم محسوس
کرتے ہیں.اس کے بعد حضرت جبرائیل آپ کو لے کر آگے چلے اور دوسرے آسمان کے دروازہ پر
بھی آپ کو وہی واقعہ پیش آیا.اور اس کے اندر داخل ہو کر آپ نے دو شخصوں کو دیکھا جنہوں نے ان
الفاظ میں آپ کو خیر مقدم کیا کہ ”مرحبا اے صالح نبی اور صالح بھائی اور آپ نے بھی انہیں سلام کہا.
Page 236
۲۲۱
اور جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت سکی" ہیں.جو خالہ زاد بھائی تھے.اسی طرح
جبرائیل علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ لے کر تیسرے اور چوتھے اور پانچویں آسمان میں سے گذرے جن
میں آپ نے علی الترتیب حضرت یوسف اور حضرت اور لیں اور حضرت ہارون کو پایا.چھٹے آسمان پر آپ
کی ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی اور حضرت موسی نے بھی آپ کو اسی طرح مرحبا کہا اور آپ نے سلام
کیا.جب آپ ان سے آگے گزرنے لگے تو حضرت موسی رو پڑے جس پر آواز آئی.اے موسی" ! کیوں
روتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا.اے میرے اللہ! یہ نوجوان میرے پیچھے آیا مگر اس کی اُمت میری اُمت
کی نسبت جنت میں زیادہ داخل ہوگی.اے میرے اللہ ! میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی شخص میرے پیچھے آ کر
مجھ سے آگے نکل جائے گا.اس کے بعد آپ سا تو میں آسمان میں داخل ہوئے جہاں آپ کی حضرت
ابراہیم سے ملاقات ہوئی جو بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے.یہ بیت معمور آسمانی عبادت گاہ
کا مرکز تھا ( جس کے گویا ظل کے طور پر دنیا میں کعبتہ اللہ تعمیر ہوا تھا ) حضرت ابراہیم نے بھی آپ کو دیکھ
کر اُسی طرح مرحبا کہا جس طرح حضرت آدم نے کہا تھا.( کیونکہ وہ بھی حضرت آدم کی طرح آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے ) اور آپ نے بھی اسی طرح اُن کو سلام کہا.اس کے بعد آپ اور آگے بڑھے اور وہاں پہنچے جہاں اس وقت تک کسی بشر کا قدم نہیں پہنچا تھا.یہاں آپ نے اپنے اوپر سے بہت سی قلموں کے چلنے کی آواز سنی ( جو گو یا قضا و قدر کی قلمیں تھیں ) اس کے
بعد آپ کو اپنے سامنے ایک بیری کا درخت نظر آیا جو گویا زمینی تعلقات کے لیے آسمان کا آخری نقطہ تھا
اور اس کے ساتھ سے جنت مالی شروع ہوتی تھی.اس بیری کے درخت کے پھل اور پتے بڑے بڑے
اور عجیب و غریب قسم کے تھے.جب آپ نے اس درخت کو دیکھا تو اس پر ایک فوق البیان اور گونا گوں
تجلی کا ظہور ہوا جس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ الفاظ میں یہ طاقت نہیں کہ انہیں بیان کرسکیں.اس
بیری کے نیچے چار دریا بہہ رہے تھے جن کے متعلق جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے دو دریا تو دنیا
کے ظاہری دریا نیل وفرات ہیں اور دو باطنی دریا ہیں جو جنت کی طرف کو بہتے ہیں.اس موقع پر آپ کو
حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل وصورت میں نظر آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ چھ سو پروں سے آراستہ
ہیں.اس کے بعد آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ آپ خدائے ذوالجلال کے
لے : یہ فقرہ حضرت موسیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ حسد کے طور پر نہیں تھا بلکہ ایک طبعی رشک کا اظہار تھا جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ارفع شان کو ظاہر کرنے کے لیے غالبا خدائی تصرف کے ماتحت کرایا گیا.منہ
Page 237
۲۲۲
دربار میں پیش ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور بعض بشارات دیں اور آخر کار
خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ آپ کی اُمت کے لیے رات دن میں پچاس نمازیں فرض کی گئی
ہیں.آپ یہ حکم لے کر واپس آئے تو راستہ میں حضرت موسیٰ نے آپ کو روک کر پوچھا کہ آپ کو کیا
احکام ملے ہیں؟ آپ نے پچاس نمازوں کا حکم بیان کیا.حضرت موسی“ یہ حکم سن کر چونک پڑے اور کہا کہ
میں بنی اسرائیل کے ساتھ واسطہ پڑنے کی وجہ سے صاحب تجربہ ہوں.آپ کی امت کو اتنی نمازوں کی ہرگز
برداشت نہ ہوگی پس آپ واپس جائیں اور خدا سے اس حکم میں تخفیف کی درخواست کریں.آپ گئے
اور اللہ تعالیٰ نے پچاس میں دس کی کمی کر کے چالیس نمازوں
کا حکم دیا.مگر واپسی پر حضرت موسیٰ نے پھر روکا
اور کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں آپ واپس جا کر مزید رعایت مانگیں.اس پر آپ پھر گئے اور دس کی مزید
رعایت منظور ہوئی.غرض اس طرح حضرت موسیٰ کے مشورہ پر آپ بار بار خدا کے دربار میں گئے اور بالآخر
اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازوں کا حکم دیا.اس پر حضرت موسیٰ نے آپ کو پھر روکا اور مزید رعایت کے لیے
واپس جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں اور وہ اس سے بھی کم عبادت کو نباہ
نہیں سکے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے
شرم آتی ہے.اس پر غیب سے آواز آئی.اے محمد ! یہ پانچ نمازیں بھی ہیں اور پچاس بھی کیونکہ ہم نے
ایک نماز کے بدلے میں دس کا اجر مقرر کر دیا ہے.اس طرح ہمارے بندوں سے تخفیف بھی ہوگئی اور
ہمارا اصل حکم بھی قائم رہا.اس کے بعد جب آپ مختلف آسمانوں میں سے ہوتے ہوئے نیچے اترے تو
آپ کی آنکھ کھل گئی.( یعنی یہ کشف کی حالت جاتی رہی ) اور آپ نے دیکھا کہ آپ اسی طرح مسجد حرام
میں لیٹے ہوئے ہیں لے
بعض روایتوں میں معراج ہی کے ذکر میں ایک گھوڑے کی قسم کی سواری براق نامی کا لایا جانا اور
آپ کا اس پر سوار ہو کر یہ سفر طے کرنا اور آپ کے سامنے دو یا تین دودھ اور شراب وغیرہ کے
پیالوں کا پیش کیا جانا وغیرہ بیان ہوا ہے مگر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظارے دراصل اسراء کے ساتھ
تعلق رکھتے ہیں اور جیسا کہ بعض متقدمین کی بھی رائے ہے.نے راویوں کی غلطی سے معراج کے ذکر میں
ل : دیکھو بخاری کتاب الصلوة وكتاب بدء الخلق و كتاب التفسير وكتاب التوحيد ومسلم ابواب الاسراء
: زرقانی جلد ۶ بحث اسراء و معراج
Page 238
۲۲۳
مخلوط ہو گئے ہیں.واللہ اعلم
دوسرا واقعہ اسراء کا ہے.اسراء بھی ایک عربی لفظ ہے جس کے معنے کسی کو رات کے وقت ایک
جگہ سے دوسری جگہ لے جانے یا سفر کرانے کے ہیں.چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روحانی سیر رات
کے وقت کرائی گئی تھی ، اس لیے اس کا نام اسراء رکھا گیا.اسراء کے متعلق جو ذکر قرآن شریف میں آتا
ہے وہ یہ ہے کہ:
سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
الَّذِي بُرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ
إنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِى أَرَيْنكَ إِلَّا فِتْنَةٌ لِلنَّاسِ "
یعنی پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو ایک رات کے دوران میں مسجد حرام سے لے کر
مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تا کہ ہم اپنے اس بندے کو اپنے
بعض نشانات دکھاویں.بے شک خدا بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے....یہ وہی موقع تھا
یہ
جب اے رسول ہم نے تجھے یہ کہا کہ تیرے رب نے اب لوگوں کو گھیر لیا ہے اور جو رؤیا ہم نے
تجھے دکھائی وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی.“
اور حدیث میں جو تفصیلات اسراء کے واقعہ کی بیان ہوئی ہیں ، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ:
ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خدائی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور ایک
گدھے سے بڑا مگر خچر سے چھوٹا جانور بُراق نامی جو نہایت خوبصورت سفید رنگ لمبے جسم کا تھا آپ کے
سامنے پیش کر کے اس پر آپ کو سوار کیا اور پھر آپ کو ساتھ لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گیا.اس جانور کا قدم اس تیزی کے ساتھ اٹھتا تھا کہ ہر قدم نظر کی انتہائی حد تک لے جاتا تھا اور آپ بہت جلد
بیت المقدس میں پہنچ گئے.یہاں آپ نے اس جانور کو اس حلقہ میں باندھ دیا جہاں گذشتہ انبیاء اسے
باندھا کرتے تھے اور پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے.یہاں گذشتہ انبیاء کی ایک جماعت جن میں
حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسی علیہم السلام خاص طور پر مذکور ہوئے ہیں، پہلے سے
موجود تھی.آپ نے ان انبیاء کے ساتھ مل کر نماز پڑھی جس میں آپ امام ہوئے اور باقی انبیاء
مقتدی بنے.اس کے بعد جبرائیل نے ( کیونکہ یہ فرشتہ جبرائیل تھا ) آپ کے سامنے دو پیالے پیش کئے.ل : سورۃ بنی اسرائیل:۲
: سورۃ بنی اسرائیل:۶۱
Page 239
۲۲۴
ان میں سے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی.آپ نے دُودھ کا پیالہ لے لیا اور شراب رڈ کر
دی.جس پر جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کی بات پہچان لی.اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی
امت بھٹکتی پھرتی ہے
اور بعض دوسری روایتوں میں اس کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ:
”جب حضرت جبرائیل آپ کے سامنے بُراق لائے اور آپ اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کچھ چکا
جس پر جبرائیل نے بُراق سے کہا.بُراق ٹھہر ٹھہر و.واللہ آج تک تم پر کوئی اس شان کا شخص سوار نہیں
ہوا.اس پر بُراق شرم سے پسینہ پسینہ ہو کر خاموش کھڑا ہو گیا.اس کے بعد آپ اس پر سوار ہو کر حضرت
جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے.راستہ میں آپ کو ایک بڑھیا ملی جسے دیکھ کر آپ
نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا آگے چلئے آگے چلئے.جب آپ آگے روانہ
ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو راستہ کے ایک طرف سے کسی نے آواز دے کر بلایا کہ محمد ادھر آؤ.مگر
جبرائیل نے آپ سے پھر کہا.چلئے آگے چلئے.جب آپ آگے آئے تو کچھ دیر کے بعد آپ کو راستہ
میں چند آدمیوں کی ایک جماعت ملی جنہوں نے ان الفاظ میں آپ کو سلام کہا کہ ”اے اول تجھ پر خدا کا
سلام ہو.اے آخر تجھ پر خدا کا سلام ہو.اے حاشر ( یعنی جمع کرنے والے ) تجھ پر خدا کا سلام ہو.“
جبرائیل نے کہا آپ بھی ان کے سلام کا جواب دیں؛ چنانچہ آپ نے بھی انہیں سلام کہا اور پھر آگے
روانہ ہو گئے.تھوڑی دیر کے بعد پھر یہی جماعت آپ کو راستہ میں ملی اور پھر انہی الفاظ میں سلام کہا اور
کچھ وقفہ کے بعد پھر تیسری دفعہ یہی واقعہ پیش آیا.اس کے بعد آپ بیت المقدس میں پہنچ گئے.یہاں جبرائیل نے آپ کے سامنے تین پیالے پیش کئے.ایک میں پانی تھا.دوسرے میں شراب تھی اور
تیسرے میں دودھ تھا.آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور باقی دونوں رڈ کر دئیے.جبرائیل نے کہا.آپ
نے فطرت کی بات اختیار کی ہے.اگر آپ پانی لیتے تو آپ کی اُمت غرق ہو جاتی اور اگر آپ شراب
کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت بھٹکتی پھرتی.پھر آپ کے سامنے حضرت آدم اور ان کے بعد کے انبیاء
لائے گئے اور آپ نے ان کا امام بن کر انہیں نماز پڑھائی.اس کے بعد جبرائیل نے آپ سے کہا کہ
وہ جو آپ نے راستہ میں بڑھیا دیکھی تھی وہ دنیا تھی اور دنیا کی عمر میں اب صرف اسی قدر وقت باقی رہ گیا
ہے جو اس بڑھیا کی عمر میں باقی رہتا ہے اور وہ جو آپ کو کوئی شخص راستہ کے ایک طرف بلاتا تھا وہ
لے : بخاری باب تفسیر سورۃ بنی اسرائیل ومسلم باب الاسراء و باب ذکر امسیح ابن مریم
م
Page 240
۲۲۵
شیطان تھا جو آپ کو راستہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا اور وہ جو آپ کو آخر میں ایک جماعت
ملی تھی اور انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا وہ خدا کے رسول حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور عیسی علیہم السلام تھے.اس کے بعد آپ مکہ کی طرف واپس لوٹ آئے ہے
یہ وہ واقعات ہیں جو معراج اور اسراء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے اور جو شخص ان
واقعات کوغور سے مطالعہ کرے گا وہ ان کی غرض و غایت کے متعلق کبھی بھی شک و شبہ میں نہیں رہ سکتا.خصوصاً جب کہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ یہ واقعات ظاہر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ وہ نہایت اعلیٰ
قسم کے کشوف تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی تصرف کے ماتحت دکھائے گئے.یہ بات تو ادنیٰ
مطالعہ سے بھی ظاہر ہے کہ معراج اور اسراء دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارفع شان اور آپ
کی اُمت کے مرتبہ کی بلندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ علاوہ اور اشارات کے دونوں کشوف میں
آپ کا گذشتہ انبیاء سے ملنا اور اُن سے آگے نکل جانا یا نماز میں ان کا امام بننا اسی حقیقت کا حامل ہے.ان کشوف میں بعض انبیاء کا خاص طور پر آپ کی ملاقات کے لیے منتخب کیا جانا بھی اپنے اندر ایک معنی رکھتا
ہے.دراصل یہ انبیاء وہی ہیں جن کی اُمتوں سے یا تو آپ کی اُمت کو خاص طور پر واسطہ پڑنے والا تھا
اور یا یہ انبیاء بعض خاص صفات کے حامل تھے اور ان کشوف میں اس حقیقت کا اظہار مقصود تھا کہ آپ کا
وجودان انبیاء کی مخصوص صفات میں بھی ان سے بالا وارفع ہے.اُمتوں کے تعلق کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ
اور حضرت موسیٰ اور ایک جہت سے حضرت ابراہیم اور حضرت آدم علیہم السلام خاص امتیاز رکھتے ہیں اور
اسی لیے اسراء اور معراج دونوں میں ان انبیاء کو خاص طور پر نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے.حضرت عیسی" تو
مسیحی اقوام کے مرکزی نقطہ تھے جو اُس زمانہ میں بھی ایک نمایاں حیثیت حاصل کر چکی تھیں.حضرت موسیٰ
نہ صرف یہودیت کے بانی مبانی تھے جن کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنقریب واسطہ پڑنے والا
تھا بلکہ وہ ایک ایسی شریعت کے لانے والے تھے جو اپنی تدوین اور تعیین اور الہامی نوعیت کی وجہ سے
اسلامی شریعت کے ساتھ بہت قریب کی مشابہت رکھتی تھی.حضرت ابرا ہیم وسیع شامی اقوام کے جد امجد
ا
ہونے کے علاوہ مسیحیت اور یہودیت اور حنیفیت اور اسلام کے لیے ایک مشترک واجب الاحترام ہستی تھے
اور بالآ خر حضرت آدم کا وجود تھا جو گویا تمام بنی نوع آدم کا اجتماعی نقطہ تھا.اس جہت سے معراج اور اسراء
میں ان انبیاء کا مخصوص طور پر چنا جانا صاف طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے تھا کہ
: ترمذی باب التفسیر و ابن کثیر تفسیر آیت اسراء بحوالہ ابن جریر از روایت انس بن مالک.ابن ہشام ذکر اسراء ملخصاً
Page 241
۲۲۶
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود میں وہ عظیم الشان ہستی مبعوث ہوئی ہے جو سید ولد آدم اور
فخر اولین و آخرین ہے اور خدا کی طرف سے یہ مقدر ہو چکا ہے کہ آپ کی اُمت کا قدم ان سب
اُمتوں پر بالا وارفع رہے.حضرت موسی" چونکہ ایک خاص سلسلہ کے بانی ہونے کی وجہ سے ان رموز سے
زیادہ آشنا تھے.انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرواز روحانی کی حقیقت کو فوراً سمجھ لیا اور
اس طبعی رشک کی وجہ سے جو فطرت انسانی کا خاصہ ہے (نہ کہ کسی حسد کی بنا پر ) اس انکشاف نے انہیں وقتی
طور پر غم میں ڈال دیا کہ ایک پیچھے آنے والا نوجوان اُن سے آگے نکلا جارہا ہے.اسراء میں حضرت
ابرا ہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسی کا راستہ پر کھڑے ہو کر آپ کو اول اور آخر اور حاشر کہہ کر پکارنا
اور سلام کرنا بھی اپنے اندر یہی لطیف اشارہ رکھتا ہے کہ ”اے نبیوں کے سرتاج ہم پہچان گئے ہیں کہ گو
آپ سب انبیاء کے آخر میں مبعوث ہوئے ہیں مگر رتبہ کے لحاظ سے آپ ہی سب سے اول ہیں اور آپ
ہی نسل آدم کا وہ مرکزی نقطہ ہیں جس کے قدموں میں مختلف اقوام عالم کا جمع ہونا مقدر کیا گیا ہے.پس لیجئے ہماری طرف سے سلام اور دعا کی پیش کش حاضر ہے اسے قبول کیجئے.“
مندرجہ بالا غرض و غایت کے اظہار کے علاوہ جو معراج اور اسراء ہر دو میں مقصود ہے ان روحانی
سفروں کی علیحدہ علیحدہ غرض اور علیحدہ علیحدہ تشریح بھی ہے اور جہاں تک ہم نے غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ
معراج تو زیادہ تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی کمالات کے اظہار کے لیے ہے اور اسراء آپ کی
ظاہری اور دنیوی ترقی کو ظاہر کرنے کے واسطے ہے.اسی لیے جہاں معراج کے واسطے آسمان کو چنا گیا
اسراء کا آخری نقطہ زمین رکھی گئی ہے.اسی طرح جہاں معراج میں آپ کا بغیر کسی سواری اور بغیر کسی ظاہری
اور مادی واسطہ کے اوپر اٹھایا جانا بیان ہوا ہے وہاں اسراء میں بُراق کی سواری کا واسطہ رکھا گیا ہے تا کہ اس
بات کی طرف اشارہ ہو کہ آپ کی اور آپ کے اتباع کی دنیوی اور ظاہری ترقی میں مادی اسباب کا بھی
دخل ہوگا گوجیسا کہ بُراق کی غیر معمولی رفتار میں اشارہ کیا گیا ہے.یہ مادی اسباب محض ایک پردہ کے طور پر
ہوں گے اور اصل سبب وہ غیبی تائید ہوگی جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گی.معراج میں آپ کا سب
نبیوں سے آگے نکل جانا اس بات کی طرف اشارہ رکھتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اپنے مقام اور مرتبہ کے
لحاظ سے سب سے بالا اور ارفع ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اپنے روحانی کمالات میں
ا
ل : حاشر کے معنی جمع کر نیوالے کے ہیں.یعنی مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر قوم اور ہر ملک کی طرف
الگ الگ رسول مبعوث ہوتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام اقوام عالم اور تمام عالم کے لیے مبعوث کیے گئے.منہ
Page 242
۲۲۷
سب شریعتوں سے فائق و برتر ہے بلکہ آپ کے فیضان روحانی میں وہ خصوصیت رکھی گئی ہے جو پہلے کسی
بشر کو حاصل نہیں ہوئی یعنی آپ کی سچی اور کامل پیروی انسان کو بلند ترین روحانی مدارج تک پہنچا سکتی ہے
اور کوئی روحانی مرتبہ ایسا نہیں ہے جہاں تک آپ کی پیروی کی برکت سے انسان
نہ پہنچ سکتا ہو.آپ سے
پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ بیشک اپنے متبعین کے لیے سرا سر رحمت و برکت بن کر آئے اور بیشک انہوں نے
اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے خدائی انعامات کے دروازے کھولے لیکن آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں
گذرا جس کی پیروی انسان
کو انتہائی کمالات تک پہنچانے کے لیے کافی ہو اور اسی لیے پہلی اُمتوں میں
اللہ تعالیٰ کا یہ طریق تھا کہ جب کوئی شخص کسی نبی کی کامل پیروی کے نتیجہ میں ترقی کر کے اس انتہائی روحانی
حد تک
پہنچ جاتا تھا جہاں تک یہ پیروی اُسے لے جا سکتی تھی تو اس کے بعد اگر یہ شخص اپنی استعداد اور شوق
اور کوشش کے لحاظ سے مزید روحانی ترقی کے قابل ہوتا تھا تو خدا تعالیٰ اُسے براہِ راست موهبت اور
انعام کے رنگ میں اوپر اٹھا لیتا تھا جس میں اس کے نبی متبوع کی پیروی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا لیکن
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ اور ارفع مقام ہے کہ ایک انسان آپ کی اتباع میں ہی جملہ قسم کے
روحانی مقامات تک پہنچ سکتا ہے اور یہی وہ خصوصیت ہے کہ جس کی طرف آپ کی اس روحانی پرواز میں
اشارہ کیا گیا ہے جو معراج کے سفر میں آپ کو کرائی گئی اور اسی حقیقت کی طرف قرآن شریف کی اس
آیت میں اشارہ ہے کہ:
وَلكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيْنَ
یعنی "محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) صرف ایک رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النبین بھی ہیں.“ جن کی مہر تصدیق
سے انسان
کو ہر قسم کے اعلیٰ ترین روحانی انعامات مل سکتے ہیں اور کوئی روحانی مرتبہ آپ کے اشباع کی
رسائی سے باہر نہیں ہے.معراج میں جن نبیوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی وہ یہ ہیں :
حضرت آدم ، حضرت عیسی ، حضرت سکی ، حضرت یوسف، حضرت ادریس ، حضرت ہارون ، حضرت
موسیٰ اور حضرت ابرا ہیم علیہم السلام.ان آٹھ نبیوں میں سے دو تو صرف ایک ضمنی تعلق کی وجہ سے اس نظارہ میں آئے ہیں.یہ دو نبی
حضرت بیچی اور حضرت ہارون ہیں جن میں سے مقدم الذکر نبی حضرت عیسی کے خالہ زاد بھائی ہونے کے
: مسلم ابواب الاسراء عَنْ ثَابِتٍ بَنَا نِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ
: سورۃ احزاب : ۴۱
Page 243
۲۲۸
علاوہ اُن کے لیے بطور ارہاص کے بھی تھے اور مؤخر الذکر نبی حضرت موسیٰ“ کے نائب تھے اور بھائی بھی
تھے.پس اس جسمانی اور روحانی تعلق کی وجہ سے یہ دو نبی اس نظارہ میں شامل کئے گئے.لیکن ایک لطیف
بات یہ ہے کہ جہاں حضرت بیٹی کو بوجہ جدا اور علیحدہ حیثیت رکھنے کے حضرت عیسی کے ساتھ رکھا گیا وہاں
حضرت ہارون کو حضرت موسی کی ماتحتی کی وجہ سے ان سے نیچے کے مگر متصل آسمان میں دکھایا گیا.باقی جو
چھ انبیاء ہیں اُن میں سے حضرت عیسی" اور حضرت موسیٰ اور حضرت ابرا ہیم اور حضرت آدم کی خصوصیات
اوپر بیان ہو چکی ہیں کہ وہ اپنی اپنی نسل اور اپنی اپنی اُمت کے نمائندوں کی حیثیت میں دکھائے گئے ہیں اور
بقیہ دو انبیاء یعنی حضرت یوسف اور حضرت ادریس کی خصوصیت خود حدیث میں اس طرح مذکور ہے کہ
حضرت یوسف اپنے خدا داد حسن ذاتی کی وجہ سے اور حضرت ادریس اپنے مخصوص علو مکانی کی وجہ سے
ممتاز تھے.اور انہیں اس نظارہ میں لاکر یہ اظہار مقصود تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ان امتیازی
خصائص رکھنے والے نبیوں سے بھی ان کے امتیازی خصائص میں بالا اور ارفع ہے.واللہ اعلم
معراج کا ایک نظارہ اس خاص تجلی سے تعلق رکھتا ہے جو سدرۃ المنتہی پر ہوئی جس کے متعلق
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بیان کی الفاظ میں طاقت نہیں ہے سو اس میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب الہی کی طرف اشارہ تھا جس میں محب ومحبوب میں جلوہ ہائے خاص کی نیرنگیوں کا
ظہور ہوا جس کے بیان کی کوشش تو در کنار اس کے علم کی کوشش بھی بے سود ہے؛ البتہ یہ ظاہر ہے کہ اس
نظارہ میں آپ نے خدا کی ان خاص اور ممتاز تجلیات کا مشاہدہ کیا جن کے دیکھنے کی طاقت صرف اس مقام
پرپہنچ کر ہی حاصل ہو سکتی ہے جو آپ کو حاصل ہوا.سدرہ کے نیچے چار دریاؤں کو بہتے دیکھنا جن میں دو
ظاہری دریا تھے اور دو باطنی ، اس غرض کے اظہار کے لیے تھا کہ خدا کی یہ تجلیات ہر دوصورتوں میں اثر انداز
ہوں گی.ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی.روحانی طور پر بھی اور دنیوی رنگ میں بھی.اور چار کے عدد میں
یہ اشارہ تھا کہ آپ کی اُمت پر ظاہری اور روحانی ترقی کے دو دو دور آ ئیں گے.ایک دور ان ہر دو قسم کی
تجلیات کا خود آپ کے وجود باجود سے شروع ہوگا اور ایک بعد کے زمانہ میں آئے گا.جب کہ مسلمان
اپنے درمیانی زمانہ میں گر کر پھر دوبارہ اٹھیں گے اور اس طرح ہر دور میں دو دو تجلیات کا ظہور ہو کر چار
نہریں مکمل ہو جائیں گی.بالآ خر پنجگانہ نماز کے فرض کئے جانے کا نظارہ ہے.اس کا ایک حصہ تو ظاہر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے
ل : مسلم ابواب الاسراء عَنْ ثَابِتٍ بَنَا نِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ
Page 244
۲۲۹
تعبیر سے خارج ہے لیکن پچاس سے پانچ تک کی کمی کا منظور ہونا ایک نہایت لطیف روحانی نظارہ ہے جس
میں اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اصل تعداد جو فرض کی جانیوالی تھی وہ پانچ ہی تھی مگر ساتھ ہی یہ مقدر تھا
کہ ان پانچ نمازوں کا ثواب پچاس کے برابر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ اُمت محمدیہ کو ان کی
نیکیوں کا بدلہ بڑھ چڑھ کر عطا کیا جائے ، اس لیے یہ نمازیں ابتدا میں پچاس کی صورت میں فرض کی گئیں اور
پھر ایک لطیف رنگ میں جس میں ضمنی طور پر اللہ تعالیٰ کی شفقت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت کا
اظہار بھی مقصود ہے یہ تعداد گھٹا کر پانچ کر دی گئی اور باتوں باتوں میں مسلمانوں کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ
تمہارے متعلق یہ اندیشہ کیا گیا ہے کہ تم ان پانچ نمازوں کی ادائیگی میں بھی سستی نہ دکھاؤ.اس لیے دیکھنا
تم اس میں سست نہ ہونا.ان حقائق کے علاوہ معراج میں اور بھی بہت سے اشارات تھے مگر ایک تاریخی
مضمون میں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں نکالی جاسکتی.اسراء کا واقعہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اس تعلق کی طرف اشارہ کرنے والا تھا جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کی اُمت کو عنقریب دوسری اُمتوں کے ساتھ پڑنے والا تھا نیز اس میں اُن آزمائشوں پر
متنبہ کرنا مقصود تھا جو آپ کے متبعین کو ان کی ترقی کے زمانہ میں پیش آنے والی تھیں.اس واقعہ میں سب
سے پہلا اشارہ یہ تھا کہ اب جو اسلام پر ایک تنگی کا زمانہ ہے اسے ہم عنقریب دور کر دیں گے اور مصائب کی
موجودہ تاریکی دن کی روشنی میں بدل جائے گی.چنانچہ آیت اسراء میں ”رات کا لفظ استعمال کیا جانا اسی
حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کیونکہ تصویری زبان میں تنگی اور مصیبت کا زمانہ رات کے وقت سے تعبیر کیا
جاتا ہے.پھر اس سفر کی ابتدا اور انتہا کے لیے مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے الفاظ کا بیان کیا جانا اس غرض
سے ہے کہ اے مسلمانو ! اب تک تمہارا واسطہ صرف قدیم عربی مذہب و تمدن کے ساتھ رہا ہے جس کا مرکز
مسجد حرام ہے لیکن اب وقت آتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ بھی تمہارا واسطہ پڑے گا اور
تمہاری توجہ کا مرکز مسجد حرام سے وسیع ہو کر یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مرکز بیت المقدس تک جاپہنچے
گا.چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ہجرت کے بعد اسلام کا محاذ غیر معمولی طور پر وسیع ہو کر یہودیت اور میسحیت کے
مقابل پر آ گیا اور اسراء میں جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ لفظ بلفظ پوری ہوئی.اس کے بعد بُراق کی سواری کا منظر ہے جس کے متعلق اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اس سے یہ مرا تھی
کہ جو مقابلہ دوسری قوموں کے ساتھ مسلمانوں کو پیش آنے والا ہے اس میں بیشک مسلمانوں کی کامیابی
بظاہر مادی اسباب کے ماتحت نظر آئے گی مگر ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی طاقت
Page 245
۲۳۰
ودیعت کی جائے گی جس میں ان نتائج کو جو خدا پیدا کرے گا ان کے ظاہری اسباب سے کوئی نسبت نہیں
ہوگی اور مسلمانوں کی سواری گویا بجلی کی طرح اُڑتی ہوئی آگے نکل جائے گی.چنانچہ ایسا ہی ہوا.تیسرے اس روحانی نظارہ میں یہ اشارہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جس نئے ماحول کا دروازہ کھولا جارہا
ہے.اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلام کے لیے ہر قسم کی برکات رکھی ہیں.جیسا کہ فرمایا.بُرَكْنَا حَوْلَهُ
یعنی ہم نے اس نئے میدان کے ماحول کو تمہارے لیے بابرکت بنایا ہے.اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا
کہ عرب اور اہل عرب کی حدود سے باہر نکل کر اسلام نے ایسا محسوس کیا کہ گویا یہ ماحول پہلے سے ہی انہی
کے لیے تیار کیا جا چکا تھا اور اس محاذ میں اسلام کی غیر معمولی فتوحات پہلے سے مقدر تھیں.دوران سفر میں
جو نظارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ان کی تشریح تو خود کشف کے اندر موجود ہے کہ ان
فتوحات کے زمانہ میں مسلمانوں کو دنیا کے اموال و امتعہ اپنی طرف کھینچیں گے مگر گو یہ دنیا کی نعمتوں کا
پانی پینے کی حد تک بے شک استعمال کیا جائے لیکن چونکہ اس کی کثرت غرق کر دینے کا سامان بھی اپنے
ساتھ رکھتی ہے اس لیے مسلمانوں کو اس کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہئے.ابلیس کا نظارہ عقیدہ کی
گمراہیوں اور ضلالتوں کا مجسمہ ہے اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کی فاتحانہ یلغار میں انہیں شیطانی
طاقتیں جادہ صواب سے منحرف نہ کر دیں.پھر نبیوں کی ملاقات ہے جو اپنے اندر برکت اور سلام کے
پیغام کے علاوہ یہ معنی بھی رکھتی ہے کہ آئندہ فتوحات میں دنیا کی قو میں اسلامی برکات سے متمتع ہو کر اس کی
برتری کا سکہ مانیں گی.چنانچہ یہ ایک تاریخ کا کھلا ہوا ورق ہے کہ یورپ و امریکہ کی موجودہ بیداری
اسلام ہی کے ساتھ واسطہ پڑنے کے نتیجہ میں ہے.ورنہ اسلام سے قبل یہ سب قو میں جہالت کی نیند سورہی
تھیں اور یورپ کے غیر متعصب محققین نے اسلام کے اس فیض و برکت کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا ہے
اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مغرب نے علوم جدیدہ کا پہلا سبق اسلام ہی سے سیکھا ہے.بالآخر
بیت المقدس میں پہنچ کر آپ کی اقتدا میں گذشتہ نبیوں کے نماز پڑھنے کا نظارہ ہے.مگر یہ نظارہ ایسا ہے
جو خود اپنی آپ تفسیر ہے جس کے لیے کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں.اسی طرح اسراء میں بعض اور
حقائق بھی ہیں مگر ہم اختصار کے خیال سے صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں.الغرض معراج اور اسراء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نہایت اعلیٰ درجہ کے کشوف تھے جن میں
آپ کو آپ کی اور آپ کی اُمت کی آئندہ فتوحات اور ترقیوں کے نظارے دکھائے گئے اور بعد کے
: فال آف دی رومن ایمپائر مصنفہ گین اور انسائیکلو پیڈیا برٹیز کا.له : سورۃ بنی اسرائیل : ۲
Page 246
۲۳۱
واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ کشوف خدا کی طرف سے تھے کیونکہ ان میں آپ کو جو کچھ دکھایا گیا اسی
طرح وقوع پذیر ہوا اور اب تک ہو رہا ہے اور آئندہ ہو گا.اب دیکھو کہ اس عظیم الشان پہلو کے مقابلہ پر
محض ظاہری اور جسمانی سفر کو کیا حقیقت حاصل ہے.اگر ان سفروں کو ظاہری جسمانی سفر قرار دیا جائے تو
اس سے زیادہ اس کے معنے نہیں بنتے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ماتحت آپ کو ایک خارق
عادت رنگ میں جسمانی طور پر مکہ سے اُٹھا کر بیت المقدس تک پہنچا دیا اور زمین سے اُٹھا کر آسمانوں کی
سیر کرادی.یہ بیشک ایک بہت پر لطف اور مقتدرانہ نظارہ سمجھا جاسکتا ہے مگر اسے اس عظیم الشان حقیقت
سے جو ان روحانی مناظر میں مخفی ہے جس کا دامن ہجرت یثرب سے لے کر گویا قیامت تک پھیلا ہوا ہے
کچھ دور کی بھی نسبت نہیں مگر افسوس ہے کہ خود مسلمان کہلانے والوں کا ایک طبقہ بھی اسے ایک عجوبہ نمائی
سے زیادہ حیثیت نہیں دینا چاہتا؟ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان روحانی مناظر میں اس کے بڑے بڑے
نشانات مخفی ہیں.یہ بھی یا درکھنا چاہیئے کہ اس قسم کے کشوف کم و بیش سبھی انبیاء کو ہوتے آئے ہیں اور سارے
نبیوں کو ہی اُن کی اُمتوں کے آئندہ حالات کافی الجملہ نظارہ کرایا جاتا رہا ہے اور اسی لئے بعض صوفیا نے
لکھا ہے کہ معراج بھی ہر نبی کو ہوا ہے اور حضرت موسیٰ کے کشف روحانی کا ذکر تو خود قرآن شریف میں
بھی آتا ہے مگر فکر ہر کس بقدر ہمت اوست.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظارہ دکھایا گیا اور جو
معراج آپ کو نصیب ہوا وہ اپنی بلندی اور اپنی وسعت اور اپنے گونا گوں کوائف میں ایک ایسی ارفع
شان رکھتا ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّالِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ
معراج اور اسراء کے وقوع کی تاریخ کے متعلق مؤرخین میں اختلاف ہے مگر روایات کا کثیر حصہ اس
طرف گیا ہے کہ یہ نظارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت یثرب سے کچھ عرصہ پہلے دکھلائے گئے تھے
اور کم از کم اسراء کے کشف کی جو تشریح ثابت ہوتی ہے وہ اسی خیال کی مؤید ہے کہ اسراء کا کشف ہجرت
کے قریب ہی ہوا تھا اور امام بخاری نے بھی جن کا پایہ روایت میں بہت بلند مانا گیا ہے اسراء اور معراج کو
ہجرت کے واقعات سے معا پہلے لکھا ہے.ہے پس اکثر مورخین کا یہ خیال درست معلوم ہوتا ہے کہ اسراء اور
معراج ہجرت سے کم و بیش ایک سال پہلے وقوع پذیر ہوئے اس طرح ان کا زمانہ ۱۲ نبوی یا ابتداء۱۳ قرار
پاتا ہے.اور اسراء کے متعلق تو یقیناً یہی صحیح ہے گو معراج کا واقعہ غالبا اس سے پہلے کا ہے.ان کی آپس
کی ترتیب کے متعلق بھی مؤرخین میں اختلاف ہے.جو لوگ ان دونوں سفروں کو ایک ہی سفر یا ایک ہی سفر
لے: دیکھئے سورۃ کہف : ۶۱ تا ۸۳
ے : بخاری کتاب بدء الخلق
Page 247
۲۳۲
کے دو حصے قرار دیتے ہیں انہوں نے بالعموم اسراء کو پہلے اور معراج کو بعد میں رکھا ہے کیونکہ ان کا یہ خیال
ہے کہ پہلے آپ مکہ سے بیت المقدس تک گئے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے لیکن
ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ خیال درست نہیں ہے بلکہ اسراء اور معراج جدا جدا چیزیں ہیں.لیکن مشکل یہ
ہے کہ ان کو جدا گانہ چیزیں ماننے والوں کے درمیان بھی ان کی ترتیب کے متعلق اختلاف ہے.ابن اسحاق نے اسراء کو پہلے رکھا ہے اور معراج کو بعد میں اور اس خیال کی تائید بخاری سے بھی ہوتی ہے
جس میں اسراء اور معراج کے الگ الگ باب باندھ کر اسراء کو معراج سے پہلے بیان کیا گیا ہے.مگر
ابن سعد نے صراحت کے ساتھ اس کے خلاف رائے ظاہر کی ہے اور معتین تاریخیں بیان کر کے معراج کو
اسراء سے پہلے رکھا ہے؛ چنانچہ ابن سعد نے معراج کی تاریخ رمضان ۱۲ نبوی بیان کی ہے اور اسراء کی
ربیع الاول ۳۱۳ اور طبری کا بھی اسی طرف میلان نظر آتا ہے کہ معراج کا واقعہ اسراء سے پہلے کا ہے کیونکہ
طبری نے معراج کو ابتداء دعوئی میں رکھا ہے.یہ ہم ان تاریخوں کی تحقیق میں تو نہیں گئے مگر واقعات کے
تفصیلی مطالعہ سے ہم اس طرف ضرور مائل ہیں کہ معراج کا واقعہ اسراء سے پہلے ہوا تھا.واللہ اعلم.پنجگانہ نماز کا فرض ہونا معراج سے پہلے اسلام میں نماز کا آغاز تو ہو چکا تھا.چنانچہ ہم دیکھ چکے
ہیں کہ ابتدائے اسلام میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
اصحاب مکہ کی گھاٹیوں میں اکیلے اکیلے یا ایک ایک یا دو دومل کر نماز پڑھا کرتے تھے مگر باقاعدہ صورت
میں پانچ وقت کی نماز کا آغاز معراج میں ہوا اور اس وقت سے اسلامی عبادات کا پہلا اور سب سے بڑا رکن
اپنی موجودہ صورت میں قائم ہو گیا.یعنی اول پو پھٹنے کے بعد مگر سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز.دوسرے سورج ڈھلنے کے بعد مگر اس کے زیادہ نیچے ہونے سے پہلے ظہر کی نماز.تیسرے سورج کے
نیچے ہو جانے کے بعد مگر روشنی دھیمی پڑنے سے پہلے عصر کی نماز.چوتھے سورج کے ڈوبنے کے بعد مگر شفق
غائب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز.پانچویں شفق غائب ہونے کے بعد مگر نصف شب سے پہلے عشاء کی
نماز.ان پانچوں فرض نمازوں کے اوقات کے متعلق گو قرآن شریف نے صرف ایک اجمالی اشارہ کیا ہے.مگر حدیث میں صراحت کے ساتھ ان
کی تعیین بیان ہوئی ہے.جہاں یہ مذکور ہے کہ معراج کے بعد
حضرت جبرائیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پانچوں نمازوں کے اوقات بالتفصیل سمجھائے.لے : ابن ہشام ذکر اسراء : بخاری ابواب الاسراء والمعراج : طبقات ابن سعد جلدا
: طبری ذکر معراج ۵ : سورۃ بنی اسرائیل : ۷۹
: بخاری کتاب مواقيت الصلوة
Page 248
۲۳۳
اسلامی نماز کی ظاہری شکل وصورت جو خدائی حکم کے ماتحت قائم کی گئی ہے یہ ہے کہ نماز کی ابتدا قیام
کی حالت سے ہوتی ہے.جبکہ نماز پڑھنے والا اپنے سینہ پر ہاتھ باندھ کر خدا کے سامنے موڈبا نہ کھڑا ہوتا
ہے.اس کے بعد رکوع کی حالت ہے جو گویا خدا کی تعظیم اور بندے کے تذلل کا دوسرا درجہ ہے جبکہ نماز
پڑھنے والا قیام کی حالت کو چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کے سامنے دو ہرا ہوکر جھک جاتا ہے.تیسر کی حالت
سجدہ کی ہے جو ایک درمیانی قیام کے بعد آتی ہے جبکہ نماز پڑھنے والا انتہائی عاجزی اور تذلل کی صورت
میں خدا کے سامنے زمین پر گر کر اپنی جبین نیاز اس کے آگے رکھ دیتا ہے اور چونکہ یہ حالت انتہائی تذلل اور
تعبد کی حالت ہے، اس لیے اسے ایک درمیانی وقفہ کے ساتھ دو دفعہ دہرایا جاتا ہے اور اس طرح نماز کی
ایک رکعت پوری ہو جاتی ہے.جس کے بعد اسی صورت میں دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی جاتی
ہے اور آخر میں نماز پڑھنے والا قعدہ میں دوزانو بیٹھ کر جو گویا ایک مقرب اور تسکین یافته درباری کی کیفیت
ہے، اپنی نماز کو تکمیل تک پہنچاتا ہے.نماز کی ہر حالت یعنی قیام اور رکوع اور سجدہ اور قعدہ کے لیے علیحدہ
علیحدہ کلمات جو ہر حالت کے مناسب حال دعا اور تحمید اور تسبیح وغیرہ پر مشتمل ہیں مقرر کر دیئے گئے ہیں مگر
ساتھ ہی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ علاوہ مقررہ کلمات کے نماز پڑھنے والا اپنی زبان میں بھی جس
طرح مناسب خیال کرے نماز کے اندر دعا اور تحمید اور تسبیح وغیرہ سے کام لے سکتا ہے یا نماز میں اتحاد
فی الصورت کی غرض سے یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے کہ خواہ کوئی مسلمان کسی جگہ ہو وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے
نماز ادا کرے.اور سوائے کسی ناگزیر مجبوری کے یہ بھی لازمی ہے کہ ایک محلہ یا گاؤں یا قصبہ کے سب
مسلمان مقررہ اوقات میں مسجد میں جمع ہو کر یا اگر مسجد نہ ہو تو کسی دوسری جگہ میں اکٹھے ہو کر ایک امام کی
اقتدا میں نماز ادا کیا کریں تاکہ ان کی اجتماعی زندگی کا شیرازہ بجائے منتشر ہونے کے دن بدن مضبوط
ہوتا چلا جاوے.نماز میں نشاط کی کیفیت پیدا کرنے اور خدا کے دربار میں صفائی کی حالت میں پیش ہونے
کی غرض سے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ نماز سے پہلے ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنے جسم کی ہر سہ اطراف کو
یعنی منہ ہاتھ اور پاؤں کو پانی سے دھو لیا کرے.اس عمل کو اسلامی اصطلاح میں وضو کہتے ہیں جو گویا
نماز کی اغراض کے لیے غسل کا قائم مقام ہے.الغرض معراج کے ساتھ اسلامی عبادات کے سب سے بڑے رکن کا قیام عمل میں آیا اور پانچ وقت کی
: کشتی نوح مصنفہ مقدس بانی سلسلہ احمدیہ
قرآن شریف سورۃ مائدہ : ۷
قرآن شریف سورۃ بقره : ۱۴۵
Page 249
۲۳۴
با قاعدہ نماز کا آغاز ہو گیا.حدیث میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے جس میں وہ خدا کے حضور میں
حاضر ہو کر اس سے باتیں کرتا ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ اگر نماز کو اس کے جملہ شرائط کے ساتھ ادا کیا
جائے اور دل کی توجہ بھی اس کے ساتھ ہو تو وہ ذات باری تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ایک بہترین
کیفیت کی حامل ہے.انسانی جسم اور روح میں فطری طور پر ایک ایسا رابطہ اور اتحاد رکھا گیا ہے کہ ان میں
سے ہر ایک کا چھوٹے سے چھوٹا تغیر بھی دوسرے پر ایک گہرا اثر پیدا کرتا ہے.مثلاً جسم کو اگر کوئی تکلیف
پہنچے تو فوراً روح بھی بے قرار ہونے لگتی ہے اور اگر روح کو کوئی صدمہ پہنچے تو اس کا فوری اثر جسم پر پڑتا ہے
اور جسم میں بھی ساری کیفیات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو خود جسم کو تکلیف پہنچنے کی صورت میں ظاہر
ہوتی ہیں.روح خوش ہو تو جسم پر بھی خوشی کے آثار تبسم وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اگر
روح مغموم ہو تو انسان کا چہرہ فورا غم کا نقشہ پیش کرنے لگ جاتا ہے.الغرض جسم اور روح کے درمیان
ایک فطری رابطہ اور اتحاد ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے گہرا اثر قبول کرتے ہیں.اس
لیے اسلامی شریعت میں کمال حکمت سے عبادت کا جسمانی نقشہ ایسا تجویز کیا گیا ہے جو انسانی روح میں
تعبد اور تذلل کی کیفیات پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر ایک طبعی خاصیت رکھتا ہے، چنانچہ نماز میں قیام اور
رکوع اور سجدہ اور قعدہ کی حالتیں اسی غرض و غایت کے ماتحت رکھی گئی ہیں کہ تا انسانی روح کے اندران
جسمانی کیفیات کے مناسب حال روحانی کیفیات پیدا کی جائیں اور ہر حالت کے لیے جود عایا تحمید یا تسبیح
کے الفاظ مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی اس روحانی کیفیت کے مناسب حال تجویز کئے گئے ہیں جو ہر جسمانی
کیفیت کے مقابلہ میں روح کے اندر پیدا کرنی مقصود ہے.مثلاً نماز میں سجدہ کی حالت میں جس میں
انسان اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے انتہائی تعتبر اور تذلیل کی حالت ہے.اس لیے جو الفاظ سجدہ کی حالت
میں پڑھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یعنی سُبْحَانَ رَبِّيَ الأعْلى ( میرا رب جو سب سے بالا و بلند ہے
وہ عیبوں سے پاک اور سب کمزوریوں سے منزہ ہے ) وہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کے سب سے
زیادہ حامل ہیں تا کہ انسانی روح یہ محسوس کرے کہ میں جس ہستی کے سامنے سجدہ کر رہی ہوں وہ ایک ایسی
برتر و بالا ہستی ہے کہ اس کے سامنے میرا یہی منصب ہے کہ انتہائی تعبد و تذلل کے ساتھ اس کے آگے گری
رہوں.اس احساس کے پیدا ہوتے ہی انسانی روح قرب الہی کی طرف بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور
ناممکن ہے کہ سجدہ کی حالت میں ایک انسان اپنی توجہ کو قائم رکھتے ہوئے اپنے دل میں کوئی روحانی تغیر
محسوس نہ کرے.البتہ جو لوگ نماز کو محض ایک رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں اور دل کی توجہ ان کے ساتھ
Page 250
۲۳۵
نہیں ہوتی ان کی روح بے شک نماز کے اعمال میں سے گذر کر بھی خالی کی خالی نکل آتی ہے کیونکہ
ان کے عمل میں کوئی جان نہیں ہوتی اور بے جان عمل کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتا.الغرض اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ نماز حقیقی معنوں میں مومن کی معراج ہے اور مسلمان اس
مبارک عبادت پر جتنا بھی فخر کریں وہ تھوڑا ہے.یقیناً نماز کے مقابلہ پر کسی مذہب کی کوئی عبادت نہیں ٹھہر
سکتی کیونکہ جس طرح نماز میں جسم اور روح کی ان بار یک دربار یک کیفیات کو ملحوظ رکھا گیا ہے جو تعبد کے
لیے ضروری ہیں وہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتا.پھر نماز میں ان مختلف کیفیات کو جس ترتیب کے ساتھ رکھا گیا
ہے وہ بھی فطرت انسانی کے عین مطابق ہے.سب سے پہلے درجہ پر قیام ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جس میں
سینہ پر ہاتھ باندھے ہوئے ایک مومن خدا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے.اس کے بعد رکوع ہے جو قیام اور
سجدہ کے بین بین تعبد و تذلل کا ایک درمیانی مرتبہ ہے.اس کے بعد سجدہ ہے جس میں گویا انسانی روح
اپنے خالق و مالک کی اعلیٰ اور کامل صفات کا مطالعہ کر کے اس کے سامنے بیتاب ہو کر زمین پر گر جاتی ہے
سب سے آخر میں قعدہ ہے جو سجدہ کے بعد ایک سکون کی کیفیت ہے جس میں انسان تعبد و تذلل کے
مراحل میں سے گذر کر گویا خدا کے تسلی یافتہ بندوں میں شامل ہو جاتا ہے.اس کے بعد نماز پڑھنے والا
دونوں طرف منہ پھیر کر سلام کہتا ہے اور نماز سے فارغ ہو جاتا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ اب اسے
دنیا میں واپس جا کر دوسرے لوگوں تک بھی اس سلامتی کے پیغام کو پہنچانا چاہیئے جو اُس نے اپنے خدا سے
حاصل کیا ہے.اس کے علاوہ نماز کی کوئی حالت بھی خاموشی کی حالت نہیں بلکہ ہر حالت کے ساتھ اس
حالت کے مناسب حال دعا اور تحمید اور تسبیح وغیرہ کے کلمات مقرر کر دیئے گئے ہیں تا کہ یہ مبارک کلمات جسم
کی ظاہری حالت اور دل کی باطنی توجہ کے ساتھ مل کر ایک پورا اور حقیقی نقشہ تعبد اور تذلل اور سوال کا پیدا کر
دیں.بھلا اس کامل و مکمل عبادت کے مقابلہ پر دوسرے مذاہب کا نا نایا بجانا یا کسی غیر فطری حالت میں
محض کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر کوئی الفاظ منہ سے کہہ دینا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اور پھر اسلام نے نماز کی عبادت
کو ایک اجتماعی صورت دینے کے لیے ایک ضروری شرط یہ بھی قرار دے دی ہے کہ ایک حلقہ کے سب
مسلمان باہم مل کر ایک امام کے پیچھے با ترتیب صفوں میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کریں اور ضمنی
طور پر اس روزانہ پنجوقتہ اجتماع میں بہت سے دوسرے اجتماعی مفاد کا دروازہ بھی کھول دیا گیا ہے.غرض
وضو سے لے کر اپنے اختتام تک نماز ایک نہایت ہی بابرکت عبادت ہے جس سے بڑھ کر قرب الہی کے
حصول اور دل کی طہارت کے لیے کوئی دوسری عبادت تصویر میں نہیں آسکتی اور دن رات کے مختلف وقتوں
Page 251
۲۳۶
میں پانچ نمازوں کا مقرر کیا جانا بھی اپنے اندر روحانی حفاظت اور روحانی تقویت کا ایک ایسا غیر معمولی
سامان رکھتا ہے جو یقینا کسی اور مذہب میں پایا نہیں جاتا.کیا اسلامی عبادتوں میں ظاہری بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے اپنی
عبادتوں میں ظاہری فارم یعنی شکل وصورت پر ضرورت
شکل وصورت پر زیادہ زور دیا گیا ہے سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے بغیر انہیں ناقص سمجھا
ہے
اور اصل چیز جو دل کی کیفیت سے تعلق رکھتی ہے اور جو گویا عبادت کی روح سمجھی جانی چاہیئے اس کی طرف
زیادہ توجہ نہیں دی بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ عبادت میں اصل چیز اس کی روح ہے
اس لیے اس کے واسطے کسی ظاہری شکل وصورت کے مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں صرف دل کی توجہ کافی
ہونی چاہیئے اور یہ کہ اسلام نے عبادت کی ایک فارم مقرر کر کے اور پھر اس پر ضرورت سے زیادہ زور دے
کر اس کی اصل روح کو مٹا دیا ہے.یہ وہ اعتراض ہے جو آجکل اسلامی عبادتوں کے متعلق کیا جاتا ہے،
لیکن غور کیا جائے تو یہ اعتراض بالکل فضول اور بودا ہے.یعنی نہ تو یہ خیال درست ہے کہ عبادت چونکہ دل کی
توجہ کا نام ہے اس لیے عبادتوں میں کسی فارم یعنی ظاہری شکل وصورت کے مقرر کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ
یہ درست ہے کہ اسلام نے عبادت کی ظاہری شکل وصورت پر ضرورت سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کی اصل
حقیقت کی طرف توجہ نہیں کی.یہ دونوں خیال اسلامی تعلیم کی رُو سے قطعأغلط اور بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں.پہلے ہم اس اعتراض کو لیتے ہیں کہ کیا عبادت میں کسی ظاہری شکل وصورت کے مقرر کئے جانے کی
ضرورت ہے یا نہیں ؟ سو جانا چاہیئے کہ یہ خیال کہ چونکہ عبادت کا حقیقی تعلق انسان
کی قلبی کیفیت سے ہے
اس لیے اس کے واسطے کسی ظاہری فارم یعنی شکل وصورت کی ضرورت نہیں ایک بالکل جہالت اور نادانی کا
خیال ہے کیونکہ اول تو جب جسم بھی خدا کا پیدا کردہ ہے تو اس کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی خدا کی عبادت میں
حصہ لے اور اسے اپنے خالق و مالک کی عبودیت سے خارج یا آزاد قرار دے دینا کسی طرح بھی جائز نہیں
سمجھا جاسکتا.انسان کا جسم اور اس کے سارے اعضاء اور ان اعضاء کی ساری طاقتیں خدا کی پیدا کردہ
ہیں.پس اگر روح پر خدا کی مخلوق ہونے کی وجہ سے عبادت کا فرض عائد ہوتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جسم اس
فرض کی ادائیگی سے باہر رہے.اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ:
وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ
ل : سورة بقره : ۴
Page 252
۲۳۷
یعنی ” سچا مسلمان وہ ہے کہ جو ان سب چیزوں اور سب طاقتوں کو جو خدا نے اُسے عطا کی
ہیں خواہ وہ جسمانی ہیں یا روحانی.مادی ہیں یا غیر مادی ہمارے رستے میں خرچ کرتا ہے اور
ہر ایک چیز میں سے جو ہم نے اُسے دی ہے ہما راحق نکالتا ہے.“
پس اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ عبادت کا حق صرف روح کے ذمہ ہے اور جسم اس سے آزاد ہے
بلکہ اسلامی تعلیم کی رو سے روح اور جسم دونوں اس بوجھ کے نیچے ہیں اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ ایسا ہو.دوسرے یہ ایک مسلّمہ حقیقت ہے کہ ہر روح یعنی سپرٹ کے لیے کسی نہ کسی جسم یعنی ظاہری فارم کا
ہونا ضروری ہے کیونکہ کوئی روح بغیر جسم کے زندہ نہیں رہ سکتی اور جو شخص کسی روح کو جسم کے بغیر زندہ رکھنے
کی سعی کرتا ہے وہ یقیناً بہت جلد روح کو بھی کھو بیٹھتا ہے.مثلاً بزرگوں اور افسروں کا ادب و احترام ایک
سراسر روحانی کیفیت ہے مگر کیا کوئی شخص اس جذبہ کی روح کو بغیر کسی ظاہری اور جسمانی پابندی کے زندہ
رکھ سکتا ہے؟ ہر گز نہیں.یقینا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں اور افسروں کے سامنے بھی
اسی طرح آزادی اور بے پروائی کے ساتھ رہتے ہوئے جس طرح میں اپنے ہم عمر دوستوں یا اپنے
عزیزوں وغیرہ کے ساتھ رہتا ہوں ان کے ادب و احترام کے جذ بہ کو اپنے دل میں قائم رکھ سکتا ہوں تو اس
کا یہ دعوئی غلط اور باطل ہوگا اور ایسا شخص بہت جلد ادب و احترام کی روح کو ضائع کر کے خالی ہاتھ رہ جائے
گا.دراصل فطرت انسانی کے ماتحت روح اور جسم کے درمیان ایک ایسا گہرا رابطہ اور عمیق تعلق ہے کہ کبھی
بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا اور یہ دونوں چیزیں ہر وقت ایک غیر معلوم مگر حکیمانہ قانون کے
ماتحت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں.مثلاً اگر ایک انسان تکلف کے ساتھ رونے کی شکل بنائے
تو وہ محسوس کرے گا کہ اس ظاہری تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے دل کے اندر بھی غم والم کی کیفیت پیدا ہونی
شروع ہوگئی ہے.اسی طرح اگر ایک شخص کا دل مغموم ہے مگر کسی وجہ سے اس کے ظاہری جسم میں بنسی کی
صورت پیدا کر دی جاوے تو اس کے ساتھ ہی اس کے دل کا غم خوشی میں مبدل ہونا شروع ہو جائے گا.پس عبادات میں جسم یعنی ظاہری فارم اور شکل وصورت کا تجویز کیا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جسم اور
روح ایک دوسرے کے ساتھ غیر منفک صورت میں پیوست ہیں اور جسم کو شامل کرنے کے بغیر عبادت کی
روح ہرگز زندہ نہیں رہ سکتی اور لحظہ بہ لحظہ کمزور ہو کر بہت جلد مرجاتی ہے.اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے
ہر نظام میں ہر روح کے لیے کوئی نہ کوئی جسم مقرر کیا جاتا ہے اور تعجب ہے کہ جولوگ اسلامی عبادات پر زیادہ
معترض ہیں وہی اس مزعومہ ” ظاہر پرستی میں دوسروں سے آگے نکلے ہوئے ہیں.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ
Page 253
۲۳۸
یورپ و امریکہ کے سارے نظام اور سارے تہذیب و تمدن کی بنیاد ظاہری فارم اور ضابطہ پر مبنی ہے اور
یقینا جتنا ز ورمغربی ممالک میں ہر چیز کی فارم پر دیا جاتا ہے اتنا کسی اور جگہ نظر نہیں آتا.مثلاً ایک ماتحت
کے لیے افسر کا ادب لازمی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے ادب محض ایک قلبی کیفیت کا نام
ہے لیکن کوئی مغربی حکومت اس بات پر تسلی نہیں پاتی کہ اس کے افراد صرف اپنے دل میں اپنے افسروں کا
ادب محسوس کر لیا کریں اور بس بلکہ اس کے لیے یورپ و امریکہ کی ہر حکومت میں بے شمار ضوابط مقرر ہیں
اور افسروں کے احترام کی غرض سے ماتحتوں
کو سینکڑوں ظاہری پابندیوں میں جکڑ دیا گیا ہے کیونکہ دنیاوی
معاملات میں ان لوگوں کے دل دُوسروں کی نسبت اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی جذبہ کی
روح کو بغیر ظاہری فارم کے زندہ نہیں رکھا جاسکتا.پھر کوئی وجہ نہیں کہ دینی معاملات میں اس فطری قانون
کو نظر انداز کیا جاوے.الغرض جسم کو عبادت میں شامل کرنا نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ جسم بھی خدا کی
مخلوق ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش میں حصہ لے بلکہ اس لیے بھی کہ ظاہری اور جسمانی
پابندی کے بغیر اندرونی روح کا بقا ممکن نہیں.دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے اپنی عبادات میں ظاہری شکل وصورت پر زیادہ زور دیا ہے اور
عبادت کی روح کی طرف جو اصل چیز ہے پوری توجہ نہیں دی.سو یہ اعتراض بھی بالکل غلط اور بے بنیاد ہے
کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے گو اسلام نے جسم کو عبادت میں شامل کر کے ہر عبادت کے لیے ایک
ظاہری صورت تجویز کی ہے لیکن چونکہ بہر حال روح جسم پر مقدم ہے اس لیے اسلام نے اصل زور عبادت
کی روح پر دیا ہے.بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس قدر زور عبادت کی روح پر اسلام میں پایا جاتا ہے وہ کسی
اور مذہب میں نظر نہیں آتا.چنانچہ نماز جو اسلام میں ساری عبادتوں سے افضل قرار دی گئی ہے اس کے
متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَا تِهِمْ سَاهُونَ ) الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ فى وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُونَ )
یعنی ” تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز کی اصل حقیقت سے غافل ہیں.وہ ایک ایسا
کام کرتے ہیں جو لوگوں کو تو نظر آتا ہے مگر اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے.انہوں نے صرف
برتن کو روک رکھا ہے اور اصل روح جس کے لیے یہ برتن مقرر ہے اُن کے ہاتھ سے نکل گئی ہے.“
: سورة ماعون : ۵ تا ۸
Page 254
۲۳۹
اس قرآنی آیت میں جس وضاحت اور زور کے ساتھ اور جس مؤثر انداز میں اسلامی عبادات کے
فلسفہ کو بیان کیا گیا ہے وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی دوسرا مذ ہب اس سے بہتر تعلیم
نہیں پیش کر سکتا.ان مختصر اور سادہ الفاظ میں اس غایت درجہ اہم اور نہایت وسیع مسئلہ کا ایسا نچوڑ آ جاتا
ہے کہ جس کے بعد حقیقتا کسی اور تشریح کی ضرورت نہیں رہتی اور یہ آیت ہم نے صرف مثال کے طور پر دی
ہے ورنہ اسلامی شریعت اس
قسم کی تعلیم سے بھری پڑی ہے کہ عبادات میں گو فطرت انسانی کے ازلی قانون
کے ماتحت جسم کا ہونا بھی ضروری ہے مگر اصل چیز روح ہے جس کے بغیر کسی جسم کو زندہ نہیں سمجھا جا سکتا.مثلاً
قربانی کے مسئلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَابِرِ اللهِ لَكُمْ فَيْهَا خَيْرُ * فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ
سَخَّرْنُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا
وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَيكُمْ
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ
یعنی ہم نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے خدا کی شناخت کا ایک ذریعہ بنایا ہے اور
ان میں تمہارے لیے بہت خیر و برکت رکھی گئی ہے.پس جب تم انہیں ذبح کرنے کے لیے
باندھو تو اُن پر خدا کا نام پڑھ لیا کرو اور پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر کر جاں بحق ہو جائیں تو تم ان
کا گوشت خود بھی کھاؤ اور حاجت مندوں اور فقیروں کو بھی کھلاؤ.ہم نے ان جانوروں کو اس
غرض سے تمہارے قابو میں دے رکھا ہے تا کہ تم خدا کے شکر گزار بندے بنو.مگر یا درکھو کہ ان
جانوروں کا گوشت اور خون خدا کو نہیں پہنچتا بلکہ جو چیز خدا کو پہنچتی ہے وہ اس تقویٰ کی روح ہے
جس سے تم یہ کام کرتے ہو اور ہم نے اسی تقویٰ کی روح کو تمہارے قابو میں رکھنے کے لیے یہ
طریق مقرر کیا ہے تا کہ تم اس رنگ میں جو خدا نے مقرر کر رکھا ہے اس کی بڑائی بیان کر سکو اور
اے رسول بشارت دے ان لوگوں کو جو اس رنگ میں خدا کی عبادت بجالاتے ہیں.اسی طرح حدیث میں بھی کثرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وارد ہوئے ہیں جن
میں آپ نے اسلامی عبادات کے متعلق یہ تشریح فرمائی ہے کہ ان میں اصل اور حقیقی مقصود عبادت کی روح
ا : سورۃ حج: ۳۷ ، ۳۸
Page 255
۲۴۰
ہے.چنانچہ روزہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں:
مَنْ لَمْ يَدَعُ قَوْلَ النُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ
یعنی ”جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ اور ریا کاری کو ترک نہیں کرتا اور اسی پر عامل رہتا ہے تو وہ
یا در کھے کہ خدا کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں.یعنی اس صورت میں اس کا
روزہ کوئی روزہ نہیں بلکہ وہ بلا وجہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے جس کا اسے کوئی بھی ثواب نہیں.“
پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اسلام نے اپنی مختلف عبادات میں ایسی تعلیم دی ہے کہ جس میں اس اصول کو کہ
عبادت میں اصل چیز اُس کی روح ہے عملاً ملحوظ رکھا گیا ہے.مثلاً نماز کے متعلق اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ وہ
قبلہ رخ ہو کر ادا ہونی چاہئے لیکن ایسے حالات میں جب کہ کسی مجبوری سے قبلہ رخ ہونا مشکل ہو جائے.مثلاً انسان جب کسی سواری پر سوار ہو اور سواری کا رخ اس کے قابو میں نہ ہو یا کسی وقت بادل وغیرہ کی وجہ
سے قبلہ کا رخ معلوم نہ ہو سکے تو اس قسم کی صورتوں میں اسلام کا یہ حکم ہے کہ پھر جدھر سواری کا رخ ہو یا
جس طرف انسان قیاس کرے کہ ادھر قبلہ ہے اُدھر ہی منہ کر کے نماز ادا کر لی جاوے.یا مثلا نماز کے لیے
قیام اور رکوع اور سجدہ اور قعدہ کی حالتیں لازمی قرار دی گئی ہیں لیکن بایں ہمہ اگر بیماری کی وجہ سے کوئی
شخص کھڑا نہ ہو سکے یا کوئی اور معذوری ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ بیٹھ کر ہی نماز ادا کر لے اور اگر بیٹھ
بھی نہ سکے تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لے.یہی اصول دوسری عبادتوں پر بھی چسپاں ہوتا ہے.گویا جہاں
کہیں بھی عبادت کی روح اور اس کا جسم وقتی حالات کی مجبوری کی وجہ سے آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں اور
دونوں کو ایک وقت میں اختیار نہیں کیا جا سکتا تو وہاں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جسم کو چھوڑ دو اور روح کو اختیار کر
لو.جو اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ اسلام میں اصل مقصود عبادت کی روح کو قرار دیا گیا ہے اور جسم کو محض جسم
کی ظاہری شرکت اور روح کے بقا کے لیے رکھا گیا ہے.وهو المراد.پس یہ الزام کہ اسلام نے اپنی
عبادات میں جسم کو شامل کر کے روح کو مٹا دیا ہے یا یہ کہ جسم پر زیادہ زور دے کر روح کو کمزور کر دیا ہے
بالکل غلط اور بے بنیاد ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس معاملہ میں اسلامی تعلیم ایک ایسا اعلیٰ اور وسطی اور دلکش نمونہ
پیش کرتی ہے جو نہ صرف ہر اعتراض سے بالا ہے بلکہ دنیا کا کوئی دوسرا مذ ہب اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا.اور پھر جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اسلام نے اپنی عبادات کے لیے جسم بھی ایسے تجویز کئے ہیں کہ ان
ا : بخاری بحوالہ مشکوۃ باب تنزية الصوم
-
Page 256
۲۴۱
سے بڑھ کر عبادت کی روح کو زندہ رکھنے اور ترقی دینے کے لیے کوئی صورت خیال میں نہیں آسکتی.سلطنت ہائے روم و فارس کی باہمی جنگ اور اس اسلام سے قبل اور اسلام کے ابتدائی
زمانہ میں تمام متمدن دنیا میں سب سے
کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ وسیچ
سلطنتیں دو تھیں.سلطنت فارس اور سلطنت روم اور یہ دونوں سلطنتیں عرب کے قریب واقع تھیں.سلطنت فارس عرب کے شمال مشرق میں تھی اور سلطنت روم شمال مغرب میں.چونکہ ان سلطنتوں کی سرحد
ملتی تھی اس لیے بعض اوقات ان کا آپس میں جنگ و جدل بھی ہو جا تا تھا.اس زمانہ میں بھی جس کا اب ہم
ذکر کر رہے ہیں یہ سلطنتیں برسر پیکار تھیں اور سلطنت فارس نے سلطنت روم کو زیر کیا ہوا تھا اور اس کے کئی
قیمتی علاقے چھین لیے تھے اور اُسے برابر دباتی چلی جاتی تھی یا قریش چونکہ بت پرست تھے اور فارس کا
بھی قریباً قریباً یہی مذہب تھا.اس لیے قریش مکہ فارس کی ان فتوحات پر بہت خوش تھے مگر مسلمانوں
کی سلطنت روم سے ہمدردی تھی کیونکہ رومی سلطنت عیسائی تھی اور عیسائی بوجہ اہل کتاب ہونے اور
حضرت مسیح ناصری سے نسبت رکھنے کے بت پرست اور مجوس اقوام کی نسبت مسلمانوں کے بہت قریب
تھے.ایسے حالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر پیشگوئی فرمائی کہ گو اس وقت
روم فارس سے مغلوب ہو رہا ہے مگر چند سال کے عرصہ میں وہ فارس پر غالب آ جائے گا اور اس دن مومن
خوش ہوں گے.یہ پیشگوئی سن کر مسلمانوں نے جن میں حضرت ابوبکر" کا نام خاص طور پر مذکور ہوا ہے مکہ
میں عام اعلان کرنا شروع کیا کہ ہمارے خدا نے یہ بتایا ہے کہ عنقریب روم فارس پر غالب آئے گا.قریش
نے جواب دیا کہ اگر یہ پیشگوئی سچی ہے تو آؤ شرط لگا لو.چونکہ اس وقت تک اسلام میں شرط لگانا ممنوع
نہیں ہوا تھا.حضرت ابو بکرؓ نے اسے منظور کر لیا اور رؤساء قریش اور حضرت ابوبکر کے درمیان چند اونٹوں
کی ہار جیت پر شرط قرار پا گئی اور چھ سال کی میعاد مقرر ہوئی مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا.چھ سال کی میعاد مقرر کرنا غلطی ہے.اللہ تعالیٰ نے تو میعاد کے متعلق
بِضْعِ سِنِينَ کے الفاظ فرمائے ہیں جو عربی محاورہ کی رو سے تین سے لے کے نو تک کے لیے بولے جاتے
ہیں.یہ اس زمانہ کی بات ہے جب کہ آپ مکہ میں ہی مقیم تھے اور ہجرت نہیں ہوئی تھی اس کے بعد مقررہ
میعاد کے اندر اندر ہی جنگ نے اچانک پلٹا کھایا اور روم نے فارس کو زیر کر کے تھوڑے عرصہ میں ہی اپنا
: چیمبرس انسائیکلو پیڈیا حالات ہر قل سے : سورة روم : ۲ تا ۵
Page 257
۲۴۲
تمام علاقہ واپس چھین لیا.یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے.اس واقعہ کا سرولیم میور نے اپنی کتاب میں
یوں ذکر کیا ہے کہ:
’ جب فارس کی فتوحات کا سیلاب ابھی تک برابر بڑھا چلا جاتا تھا.محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم )
نے اپنی تیسویں سورۃ میں یہ پیشگوئی کی کہ عنقریب روم فارس پر غالب آئے گا اور جیسا کہ ہم
دیکھ چکے ہیں واقعات نے اس پیشگوئی کو سچا ثابت کیا.،،
قبائل عرب
کو تبلیغ اسلام قبائل کے دورہ کے متعلق مختصراً اوپر ذکر کیا جا چکا ہے.انبیاء تو کبھی بھی
مایوس نہیں ہوتے مگر ظاہری حالات کے لحاظ سے مکہ کی حالت اس
وقت سخت مایوس کن تھی.قریش عداوت اور ایذا رسانی میں دن بدن ترقی کرتے جاتے تھے اور موجودہ
صورت میں اُن کے مسلمان ہونے کی بظاہر بہت ہی کم امید تھی.دوسری طرف آپ کے طائف کے سفر نے
اس شہر کے متعلق بھی فی الحال کوئی امید پیدا نہیں کی تھی.انہیں حالات کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دن بدن اپنی توجہ کو دیگر قبائل عرب کی طرف زیادہ پھیرتے جاتے تھے اور چونکہ قبائل کی تبلیغ کا بہترین
ذریعہ یہ تھا کہ حج کے موقع پر مکہ اور منیٰ میں اور اشھر حرم کے دیگر ایام میں عکاظ ، مجتنہ اور ذ والمجاز کے میلوں
کے موقع پر ان کے پاس جا کر تبلیغ کی جاوے، اس لیے آپ نے ان موقعوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ
اٹھانا شروع کیا اور کثرت کے ساتھ قبائل کا دورہ شروع کر دیا.بعض اوقات حضرت ابو بکر اور حضرت علی یا
زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے.مگر جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے قریش نے اس میں بھی روک
ٹوک شروع کر دی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابولہب نے تو گویا اپنا یہ معمول کر لیا تھا کہ
جہاں آپ تشریف لے جاتے وہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور جب آپ اپنی تقریر شروع فرماتے تو وہ
شور کرنے لگتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس کی بات نہ مانو کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے اور تمہارا دین
بھی بگاڑنا چاہتا ہے.لوگ جب دیکھتے کہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہی آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو وہ بھی
تکذیب کرتے.اور بعض وقت ہنسی اور مذاق بھی اڑاتے.ابولہب کے علاوہ ابو جہل نے بھی کئی دفعہ
آپ کے پیچھے جا کر لوگوں کو آپ سے بدظن کرنے کی کوشش کی چنانچہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ
: ترمذی تفسیر سورۃ روم میں جلدا و جیم برس انسائیکلو پیڈیا حالات ہرقل و تذ کرہ بائی زین ٹائین ایمپائر
: لائف آف محمد صفحه ۱۱۹
: ابن ہشام باب عَرْضُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ : ابن سعد
Page 258
۲۴۳
ایک دفعہ جب میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے آپ کو ذ والمجاز میں دیکھا کہ آپ لوگوں
کے مجمعوں میں گھس کر تو حید کا وعظ فرماتے پھرتے تھے.اُس وقت ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے تھا اور
آپ پر خاک پھینکتا جاتا تھا اور کہتا تھا.”اے لوگو! اس کے فریب میں نہ آنا.یہ چاہتا ہے کہ تم کو لات و عزیٰ
کی پرستش سے پھیر دے.166
ایک دفعہ آپ بنو عامر بن صعصہ کے ڈیرے میں تشریف لے گئے.خوش قسمتی سے اس وقت کوئی
قریش آپ کے ساتھ نہ تھا.آپ نے انہیں توحید کا وعظ فرمایا اور اسلام کی تائید میں اُن سے مدد چاہی.جب آپ تقریر ختم کر چکے تو ان میں سے بحیرہ بن فراس نامی ایک شخص بولا.واللہ اگر یہ شخص میرے ہاتھ
آ جاوے تو میں سارے عرب کو زیر کرلوں.اور پھر آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا.اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم
نے تمہارا ساتھ دیا اور تم اپنے مخالفوں پر غالب آگئے.تو تمہارے بعد حکومت میں ہمارا حصہ ہوگا یا نہیں ؟“
آپ نے فرمایا.حکومت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے.اُس نے کہا.خوب! تمام عرب کے سامنے سینہ سپر ہم ہوں اور حکومت غیر کے ہاتھ میں جاوے! جاؤ ہمیں تمہاری
ضرورت نہیں.غرض آپ نے مختلف قبائل کا دورہ فرمایا اور بنو عامر بن صعصہ ، بنو محارب ، فزارہ ،
غسان ، مزہ ، حنیفہ، سلیم، عبس، کنده، کلب، حارث، عذره ، حضارمہ، وغیرہ سب کو باری باری اسلام کی
دعوت دی مگر سب نے انکار کیا.اور سب سے زیادہ سختی کے ساتھ انکار کرنے والے بنو حنیفہ تھے جو یمامہ
کے رہنے والے تھے.مسیلمہ کذاب جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عہد میں نبوت کا دعویٰ
کیا اسی قبیلہ کا رئیس تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبائل کا دورہ بھی ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے.ہر دو
جہان
کا بادشاہ جس کا نام لینے پر بعد کے مسلمان شہنشاہ جن کے نام سے دنیا کا نپتی تھی اپنے تختوں سے نیچے
اتر آتے تھے ، قبائل عرب کے بدوی رئیسوں کے خیموں میں جاتا ہے اور ایک ایک رئیس کے خیمہ پر دستک
دے کر خالق کونین کا پیغام پیش کرتا ہے اور پیچھے پڑپڑ کر استدعا کرتا ہے کہ یہ تمہارے بھلے کی چیز ہے اسے
لے لو.مگر ہر دروازہ اس کے لیے بند کیا جاتا ہے اور ہر خیمہ سے اس کو یہ آواز آتی ہے کہ جاؤ یہاں تمہارا
کوئی کام نہیں اور خدا کا یہ بندہ اپنے مقدس مال کی گٹھڑی اٹھا کر اگلے خیمے کا راستہ لیتا ہے.بہر حال اب اسلامی منظر چاروں طرف تاریک و تا ر تھا.مکہ میں قریش اسلام کے جانی دشمن تھے اور
ل : مسند امام احمد بن حنبل جلدم
: ابن سعد ذكر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبائل العرب
: ابن ہشام
: ابن ہشام
Page 259
۲۴۴
ہر وقت اُسے نیست و نابود کر دینے کی فکر میں رہتے تھے.طائف والوں نے اسلام کا نام لینے پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا دئیے تھے.دیگر قبائل عرب آپ کو صاف صاف جواب دے چکے تھے.گویا ظاہری اسباب کے لحاظ سے اب اسلام کے لیے ” نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن “ کی حالت تھی مگر
اسلام خدا کا بھیجا ہوا دین تھا اور اُسی نے اسے قائم کرنے کا وعدہ فرمایا تھا اور اس زمانہ میں بھی اس کی
تائید ونصرت کے وعدے ہو رہے تھے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانہ کی وحی الہی میں خصوصیت کے
ساتھ بڑے پر شوکت اور پر رعب الفاظ میں اسلام کی آئندہ ترقی اور فتوحات کے نقشے کھینچے جارہے تھے
اور مخالفین اسلام کی آئندہ ناکامیاں اور ان کی ہلاکت کی پیشگوئیاں دنیا کو سنائی جارہی تھیں.قریش ان
باتوں کو سنتے اور بے اختیار ہنس دیتے.مگر خداوند عالمیان اپنی قدرت کے زور سے یہ سب نظارے
دکھانے والا تھا اور پردہ غیب سے عنقریب کچھ ظاہر ہونے والا تھا؛ چنانچہ ناگاہ میثرب کی جانب کا کنارہ
ٹوٹ کر گرا اور اسلامی چشمہ کا پانی جو چاروں طرف راستہ بند ہونے کی وجہ سے اب تک اپنے کناروں کے
ساتھ ٹکراٹکرا کر رہ جاتا تھا بڑے زور کے ساتھ اس راستہ سے بہ نکل مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کی کیفیت
بیان کریں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ میٹر ب اور اہلِ یثرب کا مختصر سا حال تحریر کر دیں تا کہ ان واقعات کا
سمجھنا آسان ہو جاوے.
Page 260
۲۴۵
وطن سے بے وطن
میثرب اور اہل میترب مکہ کے شمال کی طرف قریباً اڑھائی سو میل کے فاصلہ پر ایک شہر ہے جس کا
نام مدینہ ہے.اب تو اس کے نام سے ساری دنیا واقف ہے کیونکہ ہمارے
آقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری دس سال یہیں گزارے اور یہیں آپ فوت ہوئے
اور یہیں آپ کا مزار مبارک ہے اور یہی ابتدا میں خلافت اسلامی کا مرکز رہا ہے مگر اسلام سے پہلے یہ شہر
ایک گمنامی کی حالت میں تھا اور اس کا نام یثرب تھا.ہجرت کے بعد رسول خدا کا مسکن ہو جانے کی وجہ سے
اس کا نام مدينة الرسول مشہور ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ صرف مدینہ رہ گیا.اسلام سے پہلے یثرب کی
آبادی مذہباً دو حصوں میں منقسم تھی.یعنی یہود اور بت پرست.یہود پھر آگے تین قبائل میں تقسیم شدہ تھے
یعنی بنو قینقاع بنونضیر اور بنو قریضہ اور بت پرستوں کی بھی دو شاخیں تھیں جن کا نام اوس اور خزرج تھا.یہی اوس اور خز رج بعد میں اسلام لا کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر انصار کے لقب سے
ملقب ہوئے.اسلام سے پہلے اوس و خزرج عموماً آپس میں برسر پیکار رہتے تھے.چنانچہ اس زمانہ میں
بھی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے درمیان ایک خطر ناک لڑائی ہوئی جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور
ہے.اس لڑائی میں اوس وخز رج کے بڑے بڑے نامورسردار کٹ کر ہلاک ہو گئے.چونکہ یہودی لوگ علمی اور مذہبی لحاظ سے ان بت پرستوں پر فوقیت رکھتے تھے اور دولت و اقتدار میں
بھی عموماً بڑھے ہوئے تھے ، اس لیے یہود کا اُن پر خاص اثر تھا.حتی کہ اگر کسی مشرک کے اولا دنرینہ نہ ہوتی
تھی تو وہ منت مانتا تھا کہ اگر میرے اولاد نرینہ ہوئی تو میں اپنے پہلے لڑکے کو یہودی بنادوں گا.یہود کے
ساتھ رہنے کی وجہ سے اوس و خزرج بھی کتب سماوی اور سلسلہ رسالت سے کچھ کچھ آشنا ہو گئے تھے اور چونکہ
یہود میں الہی نوشتوں کی رو سے ان دنوں ایک نبی کا انتظار تھا، اس لیے یہ بات اوس اور خزرج کے کانوں
تک بھی پہنچ چکی تھی کیونکہ یہود اُن سے کہا کرتے تھے کہ اب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے.وہ جب
ا : تفسیر ابن جریر زیر آیت لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ - بقره : ۲۵۷
Page 261
۲۴۶
آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دے کر بت پرستوں اور کافروں کو نیست و نابود کر دیں گے اور وہ ایک بڑی
سلطنت قائم کرے گا اور ہم اُسے مان کر دنیا میں طاقتور ہو جائیں گے.وغیرہ وغیرہ یے
یثرب میں اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور مکہ میں اشہر حرم کے اندر قبائل کا دورہ کر
رہے تھے کہ آپ کو معلوم ہوا کہ میثرب کا ایک مشہور شخص سوید بن صامت مکہ میں
آیا ہوا ہے.سوید مدینہ کا ایک مشہور شخص تھا اور اپنی بہادری اور نجابت اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے کامل
کہلاتا تھا اور شاعر بھی تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لیتے ہوئے اس کے ڈیرے پر پہنچے اور
اسے اسلام کی دعوت دی.اُس نے کہا میرے پاس بھی ایک خاص کلام ہے جس کا نام مجلہ لقمان ہے.آپ نے کہا مجھے بھی اس کا کوئی حصہ سناؤ.جس پر سوید نے اس صحیفہ کا ایک حصہ آپ کو سنایا.آپ نے اس
کی تعریف فرمائی کہ اس میں اچھی باتیں ہیں مگر فرمایا کہ میرے پاس جو کلام ہے وہ بہت بالا اور ارفع ہے
چنانچہ پھر آپ نے اُسے قرآن شریف کا ایک حصہ سنایا.جب آپ ختم کر چکے تو اس نے کہا.ہاں واقعی یہ
بہت اچھا کلام ہے اور گووہ مسلمان نہیں ہوا مگر اس نے فی الجملہ آپ کی تصدیق کی اور آپ کو جھٹلایا نہیں
لیکن افسوس ہے کہ مدینہ میں واپس جا کر اُسے زیادہ مہلت نہیں ملی اور وہ جلد ہی کسی ہنگامہ میں قتل ہو گیا.یہ جنگ بعاث سے پہلے کی بات ہے.اس کے بعد اسی زمانہ کے قریب یعنی جنگ بعاث سے قبل آپ پھر
ایک دفعہ حج کے موقع پر قبائل کا دورہ کر رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر چندا جنبی آدمیوں پر پڑی.یہ قبیلہ
اوس سے تھے اور اپنے بت پرست رقیبوں یعنی خزرج کے خلاف قریش سے مدد طلب کرنے آئے تھے.یہ
بھی جنگ بعاث سے پہلے کا واقعہ ہے.گویا یہ طلب مدد اسی جنگ کی تیاری کا ایک حصہ تھی.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی.آپ کی تقریرین کر ایک نو جوان
شخص جس کا نام ایاس تھا بے اختیار بول اُٹھا.”خدا کی قسم جس طرف یہ شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم ) ہم کو
بلاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں.“ مگر اس گروہ کے سردار نے ایک کنکروں
کی مٹھی اٹھا کر اس کے منہ پر ماری اور کہا ”چپ رہو.ہم اس کام کے لیے یہاں نہیں آئے اور اس
طرح اس وقت یہ معاملہ یونہی دب کر رہ گیا.مگر لکھا ہے کہ ایاس جب واپس وطن جا کر فوت ہونے لگا تو
اس کی زبان پر کلمہ تو حید جاری تھا.کے
اس کے کچھ عرصہ بعد جب جنگ بعاث ہو چکی تو 1 نبوی کے ماہ رجب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ل : ابن ہشام
: طبری
: ابن ہشام
زرقانی
Page 262
۲۴۷
کی مکہ میں بیٹرب والوں سے پھر ملاقات ہو گئی.آپ نے حسب ونسب پوچھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ خزرج
کے لوگ ہیں اور میثرب سے آئے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت کے لہجہ میں کہا ” کیا
آپ لوگ میری کچھ باتیں سن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ”ہاں ! آپ کیا کہتے ہیں.“ آپ بیٹھ گئے اور
ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن شریف کی چند آیات سنا کر اپنے مشن سے آگاہ کیا.ان لوگوں نے
ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا ”یہ موقع ہے.ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے سبقت لے جاویں.“ یہ کہہ کر
سب مسلمان ہو گئے.یہ چھ اشخاص تھے جن کے نام یہ ہیں:
-1
-۲
-Y
ابوامامہ اسعد بن زرارہ جو بنو نجار سے تھے اور تصدیق کرنے میں سب سے اول تھے.عوف بن حارث یہ بھی بنو نجار سے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب
کے ننھیال کا قبیلہ تھا.رافع بن مالک جو ہنوزریق سے تھے.اب تک جو قرآن شریف نازل ہو چکا تھا.وہ اس موقع
پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا ہے
قطبہ بن عامر جو بنی سلمہ سے تھے.عقبہ بن عامر جو بنی حرام سے تھے اور
جابر بن عبد اللہ بن رمان جو بنی عبیدہ سے تھے.اس کے بعد یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے عرض کیا کہ
ہمیں خانہ جنگیوں نے بہت کمزور کر رکھا ہے اور ہم میں آپس میں بہت نا اتفاقیاں ہیں.ہم یثرب میں
جا کر اپنے بھائیوں میں اسلام کی تبلیغ کریں گے.کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ ہم کو پھر جمع کر دے
پھر ہم ہر طرح آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے؛ چنانچہ یہ لوگ گئے اور ان کی وجہ سے میثرب میں اسلام
کا چرچا ہونے لگا ہے
بیعت عقبہ اولی ۱۲ نبوی سه سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بیٹرب والوں کی طرف سے یہ
ظاہری اسباب کے لحاظ سے ایک بیم ورجا کی حالت میں گذارا.آپ اکثر
لے : اس سے قبل حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعہ میں اس قسم کا ذکر گذر چکا ہے اسی ضمن میں یہ دوسرا واقعہ ہے جو
اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ قرآن شریف ساتھ ساتھ ضبط تحریر میں آتا جا تا تھا.منہ
: ابن ہشام وطبری و زرقانی
Page 263
۲۴۸
یہ خیال کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ان چھ مصدقین کا کیا انجام ہوتا ہے اور آیا بیتر ب میں کامیابی کی کوئی امید
بندھتی ہے یا نہیں.مسلمانوں کے لیے بھی یہ زمانہ ظاہری حالات کے لحاظ سے ایک بیم ورجا کا زمانہ تھا.وہ
دیکھتے تھے کہ سردارانِ مکہ اور رؤساء طائف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختی کے ساتھ رد کر چکے
ہیں دیگر قبائل عرب بھی ایک ایک کر کے اپنے انکار پر مہر لگا چکے تھے.مدینہ میں امید کی ایک کرن پیدا
ہوئی تھی مگر کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کرن مصائب و آلام کے طوفان اور شدائد کی آندھیوں میں قائم رہ سکے
گی.دوسری طرف مکہ والوں کے مظالم دن بدن زیادہ ہو رہے تھے اور انہوں نے اس بات کو اچھی طرح
سمجھ لیا تھا کہ اسلام کو مٹانے کا بس یہی وقت ہے مگر اس نازک وقت میں بھی جس سے زیادہ نازک وقت
اسلام
پر کبھی نہیں آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابی ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ
پر قائم تھے اور آپ کا یہ عزم واستقلال بعض اوقات آپ کے مخالفین کو بھی حیرت میں ڈال دیتا تھا کہ یہ
شخص کس قلبی طاقت کا مالک ہے کہ کوئی چیز اسے اپنی جگہ سے ہلانہیں سکتی.بلکہ اس زمانہ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں خاص طور پر ایک رعب اور جلال کی کیفیت پائی جاتی تھی اور مصائب کے
ان تند طوفانوں میں آپ کا سر اور بھی بلند ہوتا جاتا تھا.یہ نظارہ اگر ایک طرف قریش مکہ کو حیران کرتا تھا
تو دوسری طرف ان کے دلوں پر کبھی کبھی لرزہ بھی ڈال دیتا تھا.ان ایام کے متعلق سرولیم میورلکھتا ہے:
ان ایام میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اپنی قوم کے سامنے اس طرح سینہ سپر تھا کہ انہیں
بعض اوقات حرکت کی تاب نہیں ہوتی تھی.اپنی بالآ خر فتح کے یقین سے معمور مگر بظاہر
بے بس اور بے یار ومددگار وہ اور اس کا چھوٹا سا گر وہ اس زمانہ میں گویا ایک شیر کے منہ میں
تھے مگر اس خدا کی نصرت کے وعدوں پر کامل اعتما در رکھتے ہوئے جس نے اسے رسول بنا کر بھیجا
تھا.محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) ایک ایسے عزم کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑا تھا جسے کوئی چیز اپنی جگہ
سے ہلا نہیں سکتی تھی.یہ نظارہ ایک ایسا شاندار منظر پیش کرتا ہے جس کی مثال سوائے اسرائیل
کی اس حالت کے اور کہیں نظر نہیں آتی کہ جب اس نے مصائب و آلام میں گھر کر خدا کے
سامنے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے میرے آقا ! اب تو میں.ہاں صرف میں ہی اکیلا رہ گیا ہوں.نہیں بلکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا یہ نظارہ اسرائیلی نبیوں سے بھی ایک رنگ میں بڑھ کر تھا...محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) کے یہ الفاظ اسی موقع پر کہے گئے تھے کہ اے میری قوم کے صنادید تم نے
جو کچھ کرنا ہے کرلو.میں بھی کسی امید پر کھڑا ہوں.“
Page 264
۲۴۹
الغرض اسلام کے لیے یہ ایک بہت نازک وقت تھا.مکہ والوں کی طرف سے تو ایک گونہ ناامیدی
ہو چکی تھی مگر مدینہ میں امید کی کرن پیدا ہو رہی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ
اس طرف نظر لگائے ہوئے تھے کہ آیا مدینہ بھی مکہ اور طائف کی طرح آپ کو رد کرتا ہے یا کہ اس کی
قسمت دوسرے رنگ میں لکھی ہے؛ چنانچہ جب حج کا موقع آیا تو آپ بڑے شوق کے ساتھ اپنے گھر سے
نکلے اور منی کی جانب عقبہ کے پاس پہنچ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی.ناگاہ آپ کی نظر اہل بیثرب کی ایک چھوٹی
سی جماعت پر پڑی جنہوں نے آپ کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور نہایت محبت اور اخلاص سے آگے بڑھ کر
آپ کو ملے.اب کے یہ بارہ اشخاص تھے جن میں سے پانچ تو وہی گذشتہ سال کے مصدقین تھے اور سات
نئے تھے اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں میں سے تھے.-1
ان کے نام یہ ہیں :
ابوامامه اسعد بن زراره
عوف بن حارث
رافع بن مالک یہ پانچ اصحاب سابقہ مصدقین میں سے تھے
۴- قطبہ بن عامر
-7
-2
عقبہ بن عامر
معاذ بن حارث
ذکوان بن عبد قیس
از قبیله بنی نجار
از قبیله بنوزریق
(خزرج)
(خزرج)
( حلیف خزرج )
از بنی عوف
(خزرج)
(خزرج)
از بنی عبد الا شهل
(اوس)
از بنی عمر و بن عوف
(اوس)
-9
- 1+
ابو عبد الرحمن یزید بن ثعلبه از بنی بلی
عبادہ بن صامت
عباس بن عبادہ بن نضله از بنی سالم
11- ابوالہیثم بن تیہان
۱۲- عویم بن ساعده
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الگ ہو کر ایک گھائی میں ان سے ملے.انہوں نے یثرب
کے حالات سے اطلاع دی اور اب کی دفعہ سب نے باقاعدہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی.یہ بیعت
مدینہ میں اسلام کے قیام کا بنیادی پتھر تھی.چونکہ اب تک جہاد بالسیف فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے
Page 265
۲۵۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے صرف ان الفاظ میں بیعت لی جن میں آپ جہاد فرض ہونے کے
بعد عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے.یعنی یہ کہ ہم خدا کو ایک جانیں گے.شرک نہیں کریں گے.چوری نہیں کریں گے.زنا کے مرتکب نہیں ہوں گے.قتل سے باز رہیں گے.کسی پر بہتان نہیں باندھیں
گے اور ہر نیک کام میں آپ کی اطاعت کریں گے.بیعت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اگر تم صدق و ثبات کے ساتھ اس عہد پر قائم رہے تو تمہیں جنت نصیب ہوگی اور اگر
کمزوری دکھائی تو پھر تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ جس طرح چاہے گا کرے گا.“
یہ بیعت تاریخ میں بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے.کیونکہ وہ جگہ جہاں بیعت لی گئی تھی
عقبہ کہلاتی ہے جو مکہ اور منی کے درمیان واقع ہے عقبہ کے لفظی معنی بلند پہاڑی رستے کے ہیں.مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان بارہ نومسلمین نے درخواست کی کہ کوئی اسلامی معلم ہمارے ساتھ
بھیجا جاوے جو ہمیں اسلام کی تعلیم دے اور ہمارے مشرک بھائیوں کو اسلام کی تبلیغ کرے.آپ نے
مصعب بن عمیر کو جو قبیلہ عبدالدار کے ایک نہایت مخلص نوجوان تھے ان کے ساتھ روانہ کر دیا.اسلامی
مبلغ ان دنوں میں قاری یا مقری کہلاتے تھے کیونکہ ان کا کام زیادہ تر قرآن شریف سنانا تھا کیونکہ یہی
تبلیغ اسلام کا بہترین ذریعہ تھا.چنانچہ مصعب بھی یثرب میں مقری کے نام سے مشہور ہو گئے لے
یثرب میں اسلام کا چرچا مصعب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا جو
مدینہ میں سب سے پہلے مسلمان تھے اور ویسے بھی ایک نہایت مخلص اور
با اثر بزرگ تھے اور اسی مکان کو اپنا تبلیغی مرکز بنایا اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمہ تن مصروف ہو گئے اور
چونکہ مدینہ میں مسلمانوں کو اجتماعی زندگی نصیب تھی اور تھی بھی نسبتاً امن کی زندگی ، اس لیے اسعد بن زرارہ
کی تجویز پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جمعہ کی نماز کی ہدایت فرمائی اور اس طرح
مسلمانوں کی اشترا کی زندگی کا آغاز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ تھوڑے ہی عرصہ میں مدینہ میں گھر
گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا اور اوس اور خزرج بڑی سرعت کے ساتھ مسلمان ہونے شروع ہو گئے.بعض
صورتوں میں تو ایک قبیلے کا قبیلہ ایک دن میں ہی سب کا سب مسلمان ہو گیا؛ چنانچہ بنو عبد الاشہل کا قبیلہ بھی
اسی طرح ایک ہی وقت میں اکٹھا مسلمان ہوا تھا.یہ قبیلہ انصار کے مشہور قبیلہ اوس کا ایک ممتاز حصہ تھا اور
اس کے رئیس کا نام سعد بن معاذ تھا جو صرف قبیلہ بنوعبدالاشھل کے ہی رئیس اعظم نہ تھے بلکہ تمام قبیلہ اوس
: ابن ہشام وطبری
Page 266
۲۵۱
کے سردار تھے.جب مدینہ میں اسلام کا چرچا ہوا تو سعد بن معاذ کو یہ برا معلوم ہوا اور انہوں نے اسے روکنا
چاہا.مگر چونکہ اسعد بن زرارہ سے ان کی بہت قریب کی رشتہ داری تھی یعنی وہ ایک دوسرے کے خالہ زاد
بھائی تھے اور اسعد مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے سعد بن معاذ خود براہ راست دخل دیتے ہوئے رکتے تھے
کہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو جائے.لہذا انہوں نے اپنے ایک دوسرے رشتہ دار اسید بن الحضیر سے کہا کہ اسعد
بن زرارہ کی وجہ سے مجھے تو کچھ حجاب ہے مگر تم جا کر مصعب کو روک دو کہ ہمارے لوگوں میں یہ بے دینی نہ
پھیلائیں اور اسعد سے بھی کہ دو کہ یہ طریق اچھا نہیں ہے.اُسید قبیلہ عبدالا شھل کے ممتاز رؤساء میں سے
تھے.حتی کہ ان کا والد جنگ بعاث میں تمام اوس کا سردار رہ چکا تھا اور سعد بن معاذ کے بعد اُسید بن الحضیر
کا بھی اپنے قبیلہ پر بہت اثر تھا.چنانچہ سعد کے کہنے پر وہ مصعب بن عمیر اور اسعد بن زرارہ کے پاس گئے
اور مصعب سے مخاطب ہو کر غصہ کے لہجہ میں کہا.” تم کیوں ہمارے آدمیوں کو بے دین کرتے پھرتے ہو
اُس سے باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا.پیشتر اس کے کہ مصعب کچھ جواب دیتے اسعد نے آہستگی سے
مصعب سے کہا کہ یہ اپنے قبیلہ کے ایک با اثر رئیس ہیں ان سے بہت نرمی اور محبت سے بات کرنا؛ چنانچہ
مصعب نے بڑے ادب اور محبت کے رنگ میں اُسید سے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں بلکہ مہربانی فرما کر
تھوڑی دیر تشریف رکھیں اور ٹھنڈے دل سے ہماری بات سن لیں اور اُس کے بعد کوئی رائے قائم کریں.“
اُسید اس بات کو معقول سمجھ کر بیٹھ گئے اور مصعب نے انہیں قرآن شریف سنایا اور بڑی محبت کے پیرا یہ میں
اسلامی تعلیم سے آگاہ کیا.اُسید پر اتنا اثر ہوا کہ وہیں مسلمان ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ میرے پیچھے
ایک ایسا شخص ہے کہ جو اگر ایمان لے آیا تو ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا.تم ٹھہرو میں اسے ابھی یہاں
بھیجتا ہوں.یہ کہ کر اُسید اُٹھ کر چلے گئے اور کسی بہانہ سے سعد بن معاذ کو مصعب بن عمیر اور اسعد بن
زرارہ کی طرف بھجوا دیا.سعد بن معاذ آئے اور بڑے غضبناک ہو کر اسعد بن زرارہ سے کہنے لگے کہ
دیکھو اسعد تم اپنی قرابت داری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اور یہ ٹھیک نہیں ہے.اس پر مصعب نے اسی
طرح نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ آپ ذرا تھوڑی دیر تشریف رکھ کر میری بات سن لیں
اور پھر اگر اس میں کوئی چیز قابل اعتراض ہو تو بے شک رد کر دیں.سعد نے کہا.ہاں یہ مطالبہ تو معقول ہے
اور اپنا نیزہ ٹیک کر بیٹھ گئے اور مصعب نے اسی طرح پہلے قرآن شریف کی تلاوت کی اور پھر اپنے دلکش
رنگ میں اسلامی اصول کی تشریح کی.ابھی زیادہ دیر نہ گذری تھی کہ یہ بت بھی رام تھا.چنانچہ سعد نے
مسنون طریق پر فسل کر کے کلمہ شہادت پڑھ دیا اور پھر اس کے بعد سعد بن معاذ اور اُسید بن الحضیر دونوں
Page 267
۲۵۲
66
مل کر اپنے قبیلہ والوں کی طرف گئے اور سعد نے اُن سے مخصوص عربی انداز میں پوچھا کہ اے
بنی عبدالا شھل تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا.”آپ ہمارے سردار اور سردار ابن
سردار ہیں اور آپ کی بات پر ہمیں کامل اعتماد ہے.سعد نے کہا.” تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق
نہیں جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ اس کے بعد سعد نے انہیں اسلام کے اصول
سمجھائے اور ابھی اس دن پر شام نہیں آئی تھی کہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا اور سعد اور اسیڈ نے خود اپنے
ہاتھ سے اپنی قوم کے بت نکال کر توڑے لے
سعد بن معاذ اور اُسید بن الحضیر جو اس دن مسلمان ہوئے دونوں چوٹی کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں
اور انصار میں تو لا ریب ان کا بہت ہی بلند پایہ تھا.بالخصوص سعد بن معادؓ کو تو انصار مدینہ میں وہ پوزیشن
حاصل ہوئی جو مہاجرین مکہ میں حضرت ابو بکر کو حاصل تھی.یہ نوجوان نہایت درجہ مخلص، نہایت درجہ
وفادار اور اسلام اور بانی اسلام کا ایک نہایت جاں نثار عاشق نکلا اور چونکہ وہ اپنے قبیلہ کا رئیس اعظم بھی تھا
اور نہایت ذہین تھا.اسلام میں اُسے وہ پوزیشن حاصل ہوئی جو صرف خاص بلکہ اخص صحابہ کو حاصل تھی
اور لاریب اس کی جوانی کی موت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سعد کی موت پر تو رحمن کا
عرش بھی حرکت میں آ گیا ہے.ایک گہری صداقت پر مبنی تھا.یے
غرض اس طرح سرعت کے ساتھ اوس اور خزرج میں اسلام پھیلتا گیا.یہودخوف بھری آنکھوں کے
ساتھ یہ نظارے دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں یہ کہتے تھے کہ خدا جانے کیا ہونے والا ہے.یہ تو مدینہ کے خوش کن واقعات ہیں.جو بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد پیش آئے مگر ادھر مکہ میں یہ سال
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے واسطے نہایت تنگی اور سختی کا گذرا.قریش دن بدن اپنے مظالم
میں ترقی کرتے جاتے تھے خصوصاً جب ان کو مدینہ کے حالات سے اطلاع ہوئی تو ان کی دشمنی کی آگ
بہت ہی بھڑک اٹھی اور اُنہوں نے آگے سے بھی بڑھ کر مظالم شروع کر دیے اور بے چارے مسلمانوں پر
عرصہ حیات تنگ ہو گیا.بیعت عقبہ ثانیه ۱۳ نبوی
اگلے سال یعنی ۱۳ نبوی کے ماہ ذی الحجہ میں حج کے موقع پر اوس اور خزرج
کے کئی سو آدمی مکہ میں آئے.اُن میں ستر شخص ایسے شامل تھے جو یا تو
مسلمان ہو چکے تھے اور یا اب مسلمان ہونا چاہتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ
له : ابن ہشام
: بخاری
Page 268
۲۵۳
آئے تھے.مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ تھے.مصعب کی ماں زندہ تھی اور گومشرکہ تھی مگر ان سے
بہت محبت کرتی تھی.جب اسے ان کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ان کو کہلا بھیجا کہ پہلے مجھ سے آ کر مل
جاؤ پھر کہیں دوسری جگہ جانا.مصعب نے جواب دیا کہ ”میں ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
نہیں ملا آپ سے مل کر پھر تمہارے پاس آؤں گا.چنا نچہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر
ہوئے.آپ سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھر اپنی ماں کے پاس گئے.وہ بہت جلی بھنی بیٹھی
تھی.ان کو دیکھ کر بہت روئی اور بڑا شکوہ کیا.مصعب نے کہا ”ماں ! میں تم سے ایک بڑی اچھی بات کہتا
ہوں جو تمہارے واسطے بہت ہی مفید ہے اور سارے جھگڑوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے.“اس نے کہا وہ کیا
ہے؟ مصعب نے آہستہ سے جواب دیا.”بس یہی کہ بت پرستی ترک کر کے مسلمان ہو جاؤ اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ.وہ پکی مشرکہ تھی ، سنتے ہی شور مچادیا کہ ” مجھے ستاروں کی
قسم ہے میں تمہارے دین میں کبھی داخل نہ ہوں گی.اور اپنے رشتہ داروں کو اشارہ کیا کہ مصعب کو پکڑ
کر قید کر لیں مگر وہ بھاگ کر نکل گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مصعب سے انصار کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور ان میں سے بعض
لوگ آپ سے انفرادی طور پر ملاقات بھی کر چکے تھے.مگر چونکہ اس موقع پر ایک اجتماعی اور خلوت کی
ملاقات کی ضرورت تھی ، اس لئے مراسم حج کے بعد ماہ ذی الحجہ کی وسطی تاریخ مقرر کی گئی کہ اس دن نصف
شب کے قریب یہ سب لوگ گذشتہ سال والی گھائی میں آپ کو آکر ملیں تا کہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ
علیحدگی میں بات چیت ہو سکے اور آپ نے انصار کو تا کید فرمائی کہ اکٹھے نہ آئیں بلکہ ایک ایک دو دو کر کے
وقت مقررہ پر گھائی میں پہنچ جائیں اور سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انتظار کریں یے چنانچہ جب
مقررہ تاریخ آئی تو رات کے وقت جبکہ ایک تہائی رات جا چکی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر سے
نکلے اور راستہ میں اپنے چچا عباس کو ساتھ لیا جو ابھی تک مشرک تھے مگر آپ سے محبت رکھتے تھے اور
خاندان ہاشم کے رئیس تھے اور پھر دونوں مل کر اس گھائی میں پہنچے.ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ انصار بھی
ایک ایک دو دو کر کے آپہنچے.یہ ستر اشخاص تھے اور اوس و خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے.سب سے پہلے عباس نے گفتگو شروع کی کہ اے خزرج کے گروہ! (محمدصلی اللہ علیہ وسلم ) اپنے خاندان
: اسدالغابہ
: ابن سعد
سے : عرب کے لوگ اوس اور خزرج دونوں کو عام طور پر صرف خزرج کے نام سے یاد کرتے تھے.
Page 269
۲۵۴
میں معزز ومحبوب ہے اور وہ خاندان آج تک اس کی حفاظت کا ضامن رہا ہے اور ہر خطرہ کے وقت میں اس
کے لیے سینہ سپر ہوا ہے مگر اب محمد کا ارادہ اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس چلے جانے کا ہے.سواگر تم اسے
اپنے پاس لے جانے کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں اس کی ہر طرح حفاظت کرنی ہوگی اور ہر دشمن کے ساتھ
سینہ سپر ہونا پڑے گا.اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو بہتر ورنہ ابھی سے صاف صاف جواب دے دو کیونکہ
صاف صاف بات اچھی ہوتی ہے.البراء بن معرور جو انصار کے قبیلہ کے ایک معمر اور با اثر بزرگ تھے
نے کہا ” عباس ! ہم نے تمہاری بات سن لی ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ خود بھی اپنی زبان مبارک سے
کچھ فرما دیں اور جو ذ مہ داری ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ بیان فرما دیں.اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے قرآن شریف کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور پھر ایک مختصری تقریر میں اسلام کی تعلیم بیان فرمائی
اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس
طرح تم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہو.اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے تو میرے
ساتھ بھی معاملہ کرو.جب آپ تقریر ختم کر چکے تو البراء بن معرور نے عرب کے دستور کے مطابق آپ کا
ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا یا رسول اللہ ! ہمیں اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو حق وصداقت کے
ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے ہم لوگ تلواروں کے سایہ میں
پہلے ہیں اور مگر ابھی وہ بات ختم کرنے نہ پائے تھے کہ ابوالبیشم بن تیہان نے جن کا ذکر اوپر گذر چکا
ہے ان کی بات کاٹ کر کہا 'یا رسول
اللہ ! یثرب کے یہود کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں.آپ کا
ساتھ دینے سے وہ منقطع ہو جائیں گے.ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے
وطن میں واپس تشریف لے آویں اور ہم نہ ادھر کے رہیں اور نہ اُدھر کے.آپ نے ہنس کر فرمایا ”نہیں
نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو گا.تمہارا خون میرا خون ہو گا.تمہارے دوست میرے دوست اور تمہارے دشمن
میرے دشمن.اس پر عباس بن عبادہ انصاری نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈال کر کہا.لوگو کیا تم سمجھتے ہو کہ اس
عہد و پیمان کے کیا معنے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تمہیں ہر اسود واحمر کے مقابلہ کے لیے تیار ہونا
چاہیئے اور ہر قربانی کے لیے آمادہ رہنا چاہیئے.لوگوں نے کہا ”ہاں ہم جانتے ہیں.مگر یا رسول اللہ ! اس
کے بدلہ میں ہمیں کیا ملے گا ؟ آپ نے فرمایا: تمہیں خدا کی جنت ملے گی ، جو اس کے سارے انعاموں
میں سے بڑا انعام ہے.سب نے کہا ” ہمیں یہ سودا منظور.یا رسول اللہ ! اپنا ہاتھ آگے کریں.آپ
نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیا اور یہ ستر جاں نثاروں کی جماعت ایک دفاعی معاہدہ میں آپ کے
Page 270
۲۵۵
ہاتھ پر بک گئی.اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے.جب بیعت ہو چکی تو آپ نے اُن سے فرمایا کہ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے بارہ نقیب چنے تھے ، جو
موسی“ کی طرف سے اُن کے نگران اور محافظ تھے.میں بھی تم میں سے بارہ نقیب مقرر کرنا چاہتا ہوں جو
تمہارے نگران اور محافظ ہوں گے اور وہ میرے لیے عیسی کے حواریوں کی طرح ہوں گے اور میرے سامنے
اپنی قوم کے متعلق جوابدہ ہوں گے.پس تم مناسب لوگوں کے نام تجویز کر کے میرے سامنے پیش کرو.چنانچہ بارہ آدمی تجویز کئے گئے جنہیں آپ نے منظور فرمایا.اور انہیں ایک ایک قبیلہ کا نگران مقرر کر کے
اُن کے فرائض سمجھا دیئے اور بعض قبائل کے لیے آپ نے دو دو نقیب مقرر فرمائے.بہر حال ان بارہ
نقیبوں کے نام یہ ہیں:
ا - اسعد بن زراره ان کا ذکر اوپر گذر چکا ہے.قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار میں سے
تھے.جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی.یثرب میں
نماز جمعہ کی ابتدا انہی کے ہاتھوں سے ہوئی.اوّل درجہ کے مخلصوں
میں سے تھے.ہجرت کے بعد جنگ بدر سے پہلے فوت ہو گئے.اشهل
٢ - أسيد بن الحضير ان کا ذکر بھی گذر چکا ہے.قبیلہ اوس کے خاندان بنو عبدالاحم
تھے اور اکابر صحابہ میں شمار ہوتے تھے.ان کا والد جنگ بعاث
میں قبیلہ اوس کا قائد اعظم تھا.اُسید نہایت مخلص اور نہایت سمجھدار
تھے.حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ انصار میں سے تین اشخاص اپنی
افضلیت میں جواب نہیں رکھتے تھے یعنی اُسید بن الحضیر.سعد بن
معاذ اور عباد بن بشر اور اس میں شبہ نہیں کہ اُسید بڑے پائے کے صحابی
تھے.حضرت ابو بکر اُسید کی بڑی عزت کرتے تھے.عہد فاروقی میں
۳- ابوالھیثم مالک بن تیہان
وفات پائی.ان کا ذکر بھی اُوپر گذر چکا ہے.حلفاء بنی عبدالا شھل سے تھے.جنگ
صفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے ہو کر لڑے اور شہادت پائی.ا : طبری وابن ہشام
: ابن ہشام و ابن سعد و طبری وزرقانی
Page 271
۲۵۶
۴ - سعد بن عبادہ قبیلہ خزرج کے خاندان بنو ساعدہ سے تھے اور تمام قبیلہ خزرج کے
رئیس تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ممتاز ترین
انصار میں شمار ہوتے تھے.حتی کہ آنحضرت کی وفات پر بعض انصار نے
انہی کو خلافت کے لیے پیش کیا تھا جس کی وجہ سے وہ خلافت ابوبکر کے
سوال پر متزلزل ہو گئے تھے.حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فوت ہوئے.۵- البراء بن معرور قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سلمہ سے تھے اور بڑے معمر اور بزرگ
آدمی تھے.ہجرت سے پہلے ہی وفات پاگئے.۶ - عبد اللہ بن رواحہ قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث سے تھے اور مدینہ کے مشہور شاعر
اور اول درجہ کے مخلصین میں سے تھے.جنگ موتہ میں جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی تھی حضرت جعفر بن ابی طالب کی
شہادت کے بعد یہ امیر العسکر ہوئے اور لڑتے لڑتے شہادت پائی.ے.عبادہ بن صامت قبیلہ خزرج کے خاندان بنو عوف میں سے تھے اور علماء صحابہ میں شمار
ہوتے تھے.ان سے کئی احادیث مروی ہیں.حضرت عثمان کی
خلافت میں فوت ہوئے.سعد بن الربيع قبیلہ خزرج کے خاندان بنو ثعلبہ میں سے تھے.بڑے مخلص اور ممتاز
صحابی تھے.حضرت ابو بکر انہیں بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے.جنگ اُحد میں شہید ہوئے.۹ - رافع بن مالک ان کا ذکر اوپر گذر چکا ہے.قبیلہ خزرج کے خاندان بنی زریق میں
سے تھے.جب یہ اسلام لائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
کو وہ قرآنی سورتیں عطا فرما ئیں جو اس وقت تک نازل ہو چکی تھیں.جنگ احد میں شہید ہوئے.
Page 272
۲۵۷
۱۰.عبداللہ بن عمرو قبیلہ خزرج کے خاندان بنو سلمہ سے تھے جنگ اُحد میں شہید ہوئے
ان کی وفات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادہ
جابر بن عبداللہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ
نے بالمشافہ کلام کیا اور ان سے خوش ہو کر کہا کہ ”اے میرے بندے!
تم نے جو مانگنا ہو مانگو.تمہارے والد نے عرض کیا.اے میرے
خالق و مالک میری بس یہی خواہش ہے کہ پھر زندہ کیا جاؤں تا پھر
اسلام کے راستہ میں جان دوں.ارشاد ہوا ” ہم ایسا ضرور کر دیتے،
مگر ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ کوئی بشر اس دنیا سے گذر کر پھر اس دنیا میں
واپس نہیں آئے گا.عبداللہ بن عمرو کے متعلق یہ روایت بھی آتی ہے
کہ ایک دفعہ جنگ اُحد کے چھیالیس سال بعد کسی سیلاب کی وجہ سے
خطرہ پیدا ہوا تو اُن کی قبر کھود کر ان کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی تجویز
کی گئی.اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی نعش اسی طرح صحیح و سلامت تھی
جس حالت میں کہ انہیں دفن کیا گیا تھا.۱۱- سعد بن خیثمہ قبیلہ اوس کے خاندان بنو حارثہ میں سے تھے.جنگ بدر میں شہید
ہوئے.جب یہ جنگ بدر کے لیے مدینہ سے نکلنے لگے تو ان کے
والد نے کہا کہ ہم میں سے ایک کو گھر پر ٹھہرنا چاہیے اور چونکہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تم گھر پر ٹھہر و.مگر انہوں نے اصرار کیا اور آخر یہ تجویز ہوئی کہ اس غرض کے لئے
قرعہ ڈالا جائے؛ چنانچہ قرعہ میں ان کا نام نکلا اور وہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل آئے اور اُسی جنگ میں شہید ہوئے.۱۲- منذر بن عمرو قبیلہ خزرج کے خاندان بنو ساعدہ سے تھے اور ایک صوفی مزاج آدمی
تھے.بئر معونہ “ میں شہید ہوئے لیے
: اسدالغابہ
Page 273
۲۵۸
جب نقیبوں کا تقرر ہو چکا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چا عباس بن عبدالمطلب نے انصار سے
تاکید کی کہ انہیں بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے کام لینا چاہیئے کیونکہ قریش کے جاسوس سب طرف نظر
لگائے بیٹھے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس قول واقرار کی خبر نکل جائے اور مشکلات پیدا ہو جائیں.ابھی غالبا وہ یہ
تاکید کر ہی رہے تھے کہ گھائی کے اوپر سے رات کی تاریکی میں کسی شیطان کی آواز آئی کہ اے قریش!
تمہیں بھی کچھ خبر ہے کہ یہاں (نعوذ باللہ ) مدغم اور اس کے ساتھ کے مرتدین تمہارے خلاف کیا
عہد و پیمان کر رہے ہیں.اس آواز نے سب کو چونکا دیا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن رہے
اور فرمایا کہ اب آپ لوگ جس طرح آئے تھے اُسی طرح ایک ایک دو دو ہو کر اپنی قیام گاہوں میں واپس
چلے جائیں.عباس بن نضلہ انصاری نے کہا."یا رسول اللہ ! ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے.اگر حکم ہو تو ہم آج
صبح ہی ان قریش پر حملہ کر کے انہیں ان کے مظالم کا مزہ چکھا دیں.آپ نے فرمایا ”نہیں نہیں مجھے ابھی
تک اس کی اجازت نہیں ہے.بس تم صرف یہ کرو کہ خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے
جاؤ جس پر تمام لوگ ایک ایک دو دو کر کے دبے پاؤں گھائی سے نکل گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بھی اپنے چا عباس کے ساتھ مکہ میں واپس تشریف لے آئے.قریش کے کانوں میں چونکہ بھنک پڑ چکی
تھی کہ اس طرح رات کو کوئی خفیہ اجتماع ہوا ہے.وہ صبح ہوتے ہی اہل یثرب کے ڈیرہ میں گئے اور ان
سے کہا کہ ”آپ کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اور ہم ہر گز نہیں چاہتے کہ ان تعلقات کو خراب
کریں مگر ہم نے سنا ہے کہ گذشتہ رات محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ آپ
کا کوئی خفیہ سمجھوتہ ہوا ہے.یہ
کیا معاملہ ہے؟ اوس اور خزرج میں سے جو لوگ بت پرست تھے ان کو چونکہ اس واقعہ کی کوئی اطلاع بی تھی،
وہ سخت حیران ہوئے اور صاف انکار کیا کہ قطعا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا.عبد اللہ بن اُبی بن سلول بھی جو بعد
میں منافقین مدینہ کا سردار بنا.اس گروہ میں تھا.اس نے کہا.”ایسا ہر گز نہیں ہوسکتا.بھلا یہ ممکن ہے کہ
اہل میثرب کوئی اہم معاملہ طے کریں اور مجھے اس کی اطلاع نہ ہو؟ غرض اس طرح قریش کا شک رفع ہوا
اور وہ واپس چلے آئے.اس کے تھوڑی ہی دیر بعد انصار واپس یثرب کی طرف کوچ کر گئے لیکن ان کے
کوچ کر جانے کے بعد قریش کو کسی طرح اس خبر کی تصدیق ہوگئی کہ واقعی اہل میٹر ب نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کیا ہے جس پر ان میں سے بعض آدمیوں نے اہل میٹرب کا پیچھا کیا.قافلہ تو
نکل گیا تھا مگر سعد بن عبادہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے اُن کو یہ لوگ پکڑ لائے اور مکہ کے پتھر یلے میدان میں
لا کر خوب زدو کوب کیا اور سر کے بالوں سے پکڑ کر ادھر ادھر گھسیٹا.آخر جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب
Page 274
۲۵۹
کو جو سعد کے واقف تھے اطلاع ہوئی تو انہوں نے ان کو ظالم قریش کے ہاتھ سے چھڑا دیا.ہجرت میثرب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ رویا میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ایک دن مکہ
سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جانا ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو ہجرت کی جگہ دکھائی گئی
جو ایک باغوں اور چشموں والی جگہ تھی.چونکہ ابھی تک اس کی تشریح آپ پر نہیں کھلی تھی اور تشریح سے قبل
ایک نبی بھی بعض اوقات اپنے اجتہاد میں غلطی کر سکتا ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ:
ذَهَبَ وَهُلِيُّ إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ حَجَرُ فَإِذَا هِيَ مَدِينَةُ يَثْرِبَ
یعنی ” میرا خیال اس طرف گیا کہ یہ جگہ یمامہ یا حجر ہے ( جونجد میں دوشاداب جگہیں ہیں)
مگر وہ بیٹرب نکل آیا.“
چنانچہ جب یثرب میں اسلام کا چرچا ہونے لگا تو تب آپ پر یہ منکشف ہوا کہ ہجرت کی جگہ بیٹرب
ہے نہ کہ یمامہ یا حجر.اس کے بعد جب انصار کے ساتھ سب قول و قرار ہو چکا اور وہ ایک دفاعی عہد و پیمان
کی بیعت کر کے واپس چلے گئے تو آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اب جو لوگ جاسکیں وہ سب میثرب کی
طرف ہجرت کر جائیں.چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ میں باوجود قریش کی طرف سے
کئی قسم کی روکوں کے اکثر
مسلمان ہجرت کر گئے اور مکہ کے بہت سے مکانات خالی ہو گئے اور بالآ خر صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور ان کے اہل و عیال اور ایسے کمزور لوگ جو ہجرت کی طاقت نہ رکھتے تھے یا
جنہیں قریش ہجرت کے لیے نکلنے نہ دیتے تھے باقی رہ گئے.یہ سب مہاجرین مدینہ اور انصار کے مکانات
میں متفرق طور پر بطور مہمان کے ٹھہرے اور اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ پہنچ گئے اور مہاجرین کے واسطے آہستہ آہستہ الگ مکانات کا انتظام ہو گیا.مدینہ والوں نے جن کو
مہاجرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے اور پناہ دینے کی وجہ سے انصار کہتے ہیں نہایت
گرمجوشی کے ساتھ مہاجرین کا استقبال کیا اور اپنے حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر اُن کے ساتھ سلوک کیا.چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے سب مہاجرین کو انصار کی
تعریف میں رطب اللسان پایا ہے
خدا تعالیٰ کا نبی مہاجر کے لباس میں اب ہم اس عظیم الشان واقعہ کے قریب پہنچ گئے ہیں جس
سے اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے یعنی
ا : ابن سعد طبری وابن ہشام
: بخاری باب الہجرت : ابن ہشام، زرقانی ونیس
Page 275
۲۶۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت کر جانا.اسلامی سنہ جو
سن ہجری کہلاتا ہے اسی انقلابی تاریخ سے شمار کیا جاتا ہے.جب تمام مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے تو قریش کو اپنی سابقہ کا رروائیوں کی وجہ سے اندیشہ ہوا
کہ اس طرح تمام مسلمانوں کا وطن سے بے وطن ہو جانا ضرور کوئی رنگ لائے گا.علاوہ ازیں ان کو یہ بھی
غصہ تھا کہ ان کا شکار اُن کے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اپنی جگہ سوچا کہ کوئی ایسی تدبیر
کریں جس سے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے اور اُن کے مظالم کی پاداش کا کوئی سوال باقی نہ رہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے متعلق اجازت کے منتظر
تھے.مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے.مسلمان سب جاچکے ہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )
اب گویا اکیلا تن تنہا ہے.اس لیے اس کے متعلق کوئی ایسی تدبیر ہو کہ بس اس کا خاتمہ ہی ہو جائے ؛ چنانچہ وہ
اس خیال سے اپنے قومی مشورہ گاہ یعنی دارالندوہ میں جمع ہوئے اور باہم مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا
جاوے.اس مشورہ میں قریباً ایک سو قریش شامل تھے اور ایک ابلیس صفت معمر نجدی شیخ بھی شریک تھا.پیش آمدہ صورت حال پر گفت و شنید ہونے کے بعد مشورہ کے آخری مراحل میں یوں گفتگو ہوئی:
ایک شخص : محمد و آہنی زنجیروں سے جکڑ کر ایک کمرہ میں بند کر دو کہ و ہیں پڑا پڑا ہلاک ہو جائے.شیخ نجدی یہ رائے درست نہیں کیونکہ جب محمد کے رشتہ داروں اور متبعین کو علم ہوگا تو وہ ضرور حملہ
کر کے آئیں گے اور اس کو چھڑا لیں گے اور پھر فساد آگے سے بھی بڑھ جائے گا.دوسرا شخص : محمد کو مکہ سے جلا وطن کر دو.جب وہ ہماری آنکھوں سے دور ہو گیا اور ہمارے شہر سے
نکل گیا تو ہمیں کیا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے.ہمارے شہر کو اس فتنہ سے نجات مل جائے گی.شیخ نجدی : کیا تم نے محمد کی شیریں زبانی اور طلاقت لسانی اور سحر بیانی نہیں دیکھی.اگر وہ یہاں
سے یونہی سلامت نکل گیا تو یقین جانو کہ اس کے بہکائے میں آ کر کوئی نہ کوئی قبیلہ عرب تمہارے خلاف
اُمڈ آئے گا اور پھر تم اس کے خلاف کچھ نہ کر سکو گے.غرض اسی طرح تھوڑی دیر تک باہم گفتگو ہوتی رہی.کسی نے کچھ رائے دی اور کسی نے کچھ.آخر ابو جہل بن ہشام بولا:
ابوجہل : میری رائے تو یہ ہے کہ قریش کے ہر اک قبیلہ سے ایک ایک جوان چنا جائے اور اُن کے
ہاتھ میں تلواریں دے دی جاویں.پھر یہ لوگ ایک آدمی کی طرح اکٹھے ہو کر محمد پر حملہ کریں اور اسے قتل کر
Page 276
۲۶۱
دیں.ایسا کرنے سے اس کا خون سب قبائل قریش پر پھیل جائے گا اور بنو عبد مناف کو اتنی جرأت ہرگز
نہیں ہوگی کہ ساری قوم کے ساتھ لڑیں.پس لامحالہ ان کو اس خون کے بدلے میں دیت قبول کرنی ہوگی.سو وہ ہم دے دیں گے.شیخ نجدی رائے ہے تو بس اس شخص کی.باقی سب فضول باتیں ہیں.پس اگر کچھ کرنا ہے تو جو یہ
کہتا ہے وہ کرو.غرض اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا.قرآن شریف میں ان کے اس مشورہ کا ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے:
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ
b
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللهُ خَيْرُ الْمُكِرِينَ
اور یاد کر جبکہ کفار تیرے متعلق منصو بے کرتے تھے تا کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا
وطن سے نکال دیں.اور وہ اپنی طرف سے خوب پختہ منصوبے گانٹھ رہے تھے مگر اللہ نے بھی
اپنی جگہ تدبیر کر لی تھی اور اللہ بہتر تد بیر کرنے والا ہے.“
ادھر یہ لوگ مشورہ کر کے نکلے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے خون سے اپنے پلید ہاتھ رنگیں اور ادھر
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے اپنے نبی کو ان کے اس بد ارادے سے اطلاع دے دی اور
اجازت عطا فرمائی کہ میثرب کی طرف ہجرت کر جائیں اور آنے والی رات مکہ میں نہ گزاریں ہے
یہ اطلاع پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے.گرمیوں کے دن تھے اور دو پہر کا وقت تھا.حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول
تھا کہ صبح یا شام آپ ہمارے مکان پر
حضرت ابو بکر سے ملنے تشریف لایا کرتے تھے.اُس دن جو بے وقت آئے اور آئے بھی اس طرح کہ
آپ نے اپنا سر ایک کپڑے سے ڈھانکا ہوا تھا.تو حضرت ابو بکر نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آج کوئی
خاص بات ہے.آپ اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا.اگر یہاں کوئی غیر شخص ہو تو
اُسے ذرا باہر بھیج دیں.ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ ہی کے گھر کے لوگ ہیں.فرمایا ” مجھے
ل : ابن ہشام وطبری وا بن سعد
: سورۃ انفال: ۳۱
ے : اس صورت کو آخر میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بالآ خر عملاً یہی وقوع میں آئی.: ابن ہشام وطبری
۵ : طبری واقعات ہجرت
Page 277
۲۶۲
ہجرت کی اجازت مل گئی ہے.حضرت ابو بکر دن رات اس خبر کے انتظار میں تھے.فوراً بولے اَلصُّحْبَةُ
يَا رَسُولَ اللهِ - یعنی "یا رسول اللہ! مجھے بھی ساتھ رکھیئے گا ؟ ارشاد ہوا’ہاں..حضرت عائشہ کہتی ہیں
میں نے اس وقت تک کسی شخص کو خوشی میں روتے نہیں دیکھا تھا.مگر اب دیکھا کہ جونہی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں“ حضرت ابو بکر کے آنسو جاری ہو گئے..پھر انہوں نے آپ سے عرض کیا.یا رسول اللہ ! میں نے ہجرت کی تیاری میں دو اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر پال رکھی ہیں.ان میں
سے ایک آپ قبول فرماویں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں، مگر قیمت لوں گا.ابوبکر نے
ناچار قبول کیا اور ہجرت کی تیاری شروع ہوئی.حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی ضروری سامان
تیار کیا اور کھانا تیار کر کے ایک چمڑہ کے برتن میں بند کیا اور پھر میری بہن اسماء نے اپنے نطاق یعنی کمر پر
باندھنے والے پٹکے کے دوٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا کھانے کے برتن پر باندھ دیا اور ایک پانی کے برتن پر.اس سبب سے اُن کو ذَاتُ النِطَاقَيْنِ یعنی دو نطاقوں والی کہتے ہیں.اس کے بعد آپ حضرت ابو بکر سے
اسی رات مکہ سے نکل جانے اور غار ثور میں پناہ لینے کی قرارداد کر کے اپنے گھر واپس تشریف لے آئے.آغاز سفر ہجرت اور قریش کا تعاقب رات کا تاریک وقت تھا اور ظالم قریش جو مختلف قبائل سے
تعلق رکھتے تھے اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپ کے
مکان کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر چکے تھے اور انتظار تھا کہ صبح ہو یا آپ اپنے گھر سے
نکلیں تو آپ پر ایک دم حملہ کر کے قتل کر دیا جاوے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کفار کی
امانتیں پڑی تھیں کیونکہ باوجود شدید مخالفت کے اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے صدق و امانت کی وجہ سے
آپ کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے.لہذا آپ نے حضرت علی کو ان امانتوں کا حساب کتاب سمجھا دیا اور
تاکید کی کہ بغیر امانتیں واپس کئے مکہ سے نہ نکلنا.اس کے بعد آپ نے ان سے
فرمایا کہ تم میرے بستر پر
لیٹ جاؤ اور تسلی دی کہ انہیں خدا کے فضل سے کوئی گزند نہیں پہنچے گا.وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر
جو سرخ رنگ کی تھی اُن کے اوپر اُڑھا دی.اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلے اُس
وقت محاصرین آپ کے دروازے کے سامنے موجود تھے مگر چونکہ انہیں یہ خیال نہیں تھا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اول شب میں ہی گھر سے نکل آئیں گے.وہ اُس وقت اس قد رغفلت میں تھے
2 : بخاری باب الحجرت
: طبری وابن ہشام
: بخاری باب الہجرت وکتاب الاطعمة : ابن ہشام وطبری
Page 278
۲۶۳
کہ آپ اُن کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے اُن کے درمیان سے نکل گئے اور اُن کو خبر تک نہ ہوئی.اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ مگر جلد جلد مکہ کی گلیوں میں سے گذر رہے تھے اور تھوڑی
ہی دیر میں آبادی سے باہر نکل گئے اور غار ثور کی راہ لی.حضرت ابو بکر کے ساتھ پہلے سے تمام بات طے ہو
چکی تھی وہ بھی راستہ میں مل گئے.غار ثور جو اسی واقعہ کی وجہ سے اسلام میں ایک مقدس یادگار مجھی جاتی ہے
مکہ سے جانب جنوب یعنی مدینہ سے مختلف جانب تین میل کے فاصلہ پر ایک بنجر اور ویران پہاڑی کے اوپر
خاصی بلندی پر واقع ہے اور اس کا راستہ بھی بہت دشوار گزار ہے وہاں پہنچ کر پہلے حضرت ابو بکڑ نے اندر
گھس کر جگہ صاف کی اور پھر آپ بھی اندر تشریف لے گئے.دوسری طرف وہ قریش جو آپ کے گھر کا محاصرہ کئے ہوتے تھے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ
کے گھر کے اندر جھانک کر دیکھتے تھے تو حضرت علیؓ کو آپ کی جگہ پر لیٹا دیکھ کر مطمئن ہو جاتے تھے لیکن
صبح ہوئی تو انہیں علم ہوا کہ ان کا شکار اُن کے ہاتھ سے نکل گیا ہے.اس پر وہ ادھر اُدھر بھاگے.مکہ کی گلیوں میں
صحابہ کے مکانات پر تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا.اس غصہ میں انہوں نے حضرت علی کو پکڑا اور کچھ مارا پیٹا.حضرت ابوبکر کے مکان پر جا کر شور کیا اور ان کی صاحبزادی کو ڈانٹا ڈ پٹا مگر ان باتوں سے کیا بنتا تھا.آخر انہوں نے عام اعلان کیا کہ جو کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو
ایک سو اونٹ انعام دیئے جاویں گے ، چنانچہ کئی لوگ انعام کی طمع میں مکہ کے چاروں طرف اِدھر اُدھر نکل
گئے.خود رؤساء قریش بھی سراغ لیتے لیتے آپ کے پیچھے نکلے اور عین غار ثور کے منہ پر جاپہنچے.یہاں
پہنچ کر اُن کے سراغ رسان نے کہا کہ بس سراغ اس سے آگے نہیں چلتا.اس لیے یا تو محمد یہیں کہیں
پاس ہی چھپا ہوا ہے یا پھر آسمان پر اُڑ گیا ہے.کسی نے کہا.کوئی شخص ذرا اس غار کے اندر جا کر بھی
دیکھ آئے.مگر ایک اور شخص بولا کہ واہ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے.بھلا کوئی شخص اس غار میں جا کر
چھپ سکتا ہے.یہ ایک نہایت تاریک و تار اور خطرناک جگہ ہے اور ہم ہمیشہ سے اسے اسی طرح دیکھتے
آئے ہیں.یہ بھی روایت آتی ہے کہ غار کے منہ پر جو درخت تھا.اُس پر آپ کے اندر تشریف لے
جانے کے بعد مکڑی نے جالاتن دیا تھا اور عین منہ کے سامنے کی شاخ پر ایک کبوتری نے گھونسلا بنا کر انڈے
دے دیئے تھے.یہ روایت تو کمزور ہے لیکن اگر ایسا ہوا ہو تو ہر گز تعجب کی بات نہیں.مکڑی بعض اوقات
چند منٹ میں ایک وسیع جگہ پر جالاتن دیتی ہے اور کبوتری کو بھی گھونسلا تیار کرنے اور انڈے دینے میں کوئی
دیر نہیں لگتی.اس لیے اگر خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کے لیے ایسا تصرف فرمایا تو ہرگز بعید نہیں
Page 279
۲۶۴
ہے بلکہ اس وقت کے لحاظ سے ایسا ہونا بالکل قرین قیاس ہے.بہر حال قریش میں سے کوئی شخص آگے نہیں
بڑھا اور یہیں سے سب لوگ واپس چلے گئے لے
روایت آتی ہے کہ قریش اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ اُن کے پاؤں غار کے اندر سے نظر آتے تھے
اور ان کی آواز سُنائی دیتی تھی.اس موقع پر حضرت ابو بکر نے گھبرا کرمگر آہستہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کیا کہ 'یا رسول اللہ ! قریش اتنے قریب ہیں کہ اُن کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اور اگر وہ ذرا آگے
ہو کر جھانکیں تو ہم کو دیکھ سکتے ہیں.“ آپ نے فرمایا:
پھر فرمایا:
ہے.،،
لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
یعنی ہر گز کوئی فکر نہ کرو.اللہ ہمارے ساتھ ہے.“
وَمَاظُنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِتُهُمَا
یعنی ”اے ابو بکر ! تم ان دو شخصوں کے متعلق کیا گمان کرتے ہو جن کے ساتھ تیسرا خدا
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قریش غار کے منہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر سخت گھبرا
گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھا تو تسلی دی کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے.اس پر
حضرت ابوبکر نے رقت بھری آواز میں کہا:
إِنْ قُتِلْتُ فَاَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَإِنْ قُتِلْتَ اَنْتَ هَلَكَتِ الْأُمَّةُ _
یعنی 'یا رسول اللہ! اگر میں مارا جاؤں تو میں تو بس ایک اکیلی جان ہوں لیکن اگر خدانخواستہ
آپ پر کوئی آنچ آئے تو پھر تو گویا ساری اُمت کی اُمت مٹ گئی.“
اس پر آپ نے خدا سے الہام پا کر یہ الفاظ فرمائے کہ :
"
لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا :
یعنی ”اے ابو بکر ! ہر گز کوئی فکر نہ کرو کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم دونوں اس کی حفاظت میں
ہیں ، یعنی تم تو میری وجہ سے فکرمند ہو اور تمہیں اپنے جوش اخلاص میں اپنی جان
کا کوئی غم نہیں مگر خدا تعالیٰ
ا: زرقانی و تاریخ خمیس
: زرقانی
ے : بخاری باب مناقب المهاجرین
: سورة توبه : ۴۰
Page 280
۲۶۵
اس وقت نہ صرف میرا محافظ ہے بلکہ تمہارا بھی اور وہ ہم دونوں کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گالے
سفر ہجرت اور تعاقب سراقہ بن مالک حضرت
ابو بکڑ نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ
کو جو ایک بہت زیرک اور ہوشیار نو جوان تھے ہدایت
کی تھی کہ قریش کی حرکات کا خیال رکھیں اور روزانہ غار ثور میں اطلاع دے جایا کریں.چنانچہ وہ ایسا
کرتے تھے کہ رات کو اندھیرا ہوتے ہی غار ثور میں پہنچ جایا کرتے تھے اور رات وہیں گزار کر صبح سویرے
ہی واپس آ جایا کرتے تھے.حضرت ابو بکر کے خادم عامر بن فہیرہ کے سپر دیہ کام کیا گیا تھا کہ دن بھر بکریاں
چرائیں اور رات کو اُن کے پاس دودھ پہنچا جایا کریں.اس طرح آپ تین رات تک غار ثور میں ٹھہرے
اور اس عرصہ تک یہی انتظام جاری رہا.پھر جب قریش کے تعاقب کی کوشش میں کمی آگئی تو تیسرے دن
صبح کے وقت آپ غار سے نکلے.یہ پیر کا دن تھا اور چار ربیع الاول یا بعض مؤرخین کی تحقیق کے مطابق
یکم ربیع الاول ۱۴ نبوی مطابق ۱۲ ستمبر ۶۲۲ء کی تاریخ تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر
نے پہلے سے ایک شخص عبداللہ بن اریقط کو جو قبیلہ بنی الدیل سے تھا اور باوجود عاص بن وائل رئیس مکہ
کے ساتھ تعلق رکھنے کے قابل اعتماد تھا معقول اُجرت دینی کر کے بطور رہنما کے ساتھ چلنے کے لیے مقرر کر
رکھا تھا.یہ شخص اپنے فن کا خوب ماہر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے اسے پہلے سے
اپنی اونٹنیاں سپر د کر رکھی تھیں اور سمجھا رکھا تھا کہ تین رات کے بعد تیسرے دن کی صبح کو اونٹنیاں لے کر غار ثور
میں پہنچ جائے.چنانچہ وہ حسب قرار داد پہنچ گیا.یہ بخاری کی مشہور روایت ہے مگر مؤرخین لکھتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روانہ ہوئے تھے اور خود بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں اس کی
لے : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام جو قرآن شریف میں بھی مذکور ہے ایک خاص شان کا کلام ہے اور اس میں آپ کی
اس ارفع شان کا پتہ چلتا ہے جو حضرت موسیٰ پر آپ کو حاصل تھی.کیونکہ حضرت موسیٰ نے تو فرعون کے تعاقب کے وقت
اپنی قوم کے گھبرا جانے پر صرف یہ لفظ کہے کہ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِین.یعنی ”میرے ساتھ میرا خدا ہے وہ میرے لیے بچاؤ
کا راستہ نکال دے گا.“ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ معنا کے الفاظ استعمال فرمائے.یعنی ”میرے اور میرے
ساتھی دونوں کے ساتھ خدا ہے.آپ کے اس جملہ پر مقابلہ نظر ڈالنے سے آپ کے برتر اخلاق اور آپ کے صحابہ کے
اعلیٰ مقام اور آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کے بہتر سلوک پر بہت روشنی پڑتی ہے.منہ
: بخاری باب البجرت
: بخاری باب الحجرت
۳ : زرقانی ومحمود پاشا مصری
Page 281
۲۶۶
،،
تصدیق پائی جاتی ہے.اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ آپ رات کو روانہ ہوئے ہوں.بہر حال غار ثور
سے نکل کر آپ ایک اونٹنی پر جس کا نام بعض روایات میں القصوا بیان ہوا ہے ،سوار ہو گئے اور دوسری پر
حضرت ابو بکر اور اُن کا خادم عامر بن فہیرہ سوار ہوئے یے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے مکہ کی طرف آخری
نظر ڈالی اور حسرت کے الفاظ میں فرمایا.اے مکہ کی بستی تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے
لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے.اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا.ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے.اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے.چونکہ ابھی تک تعاقب کا ڈر تھا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اصل راستہ
چھوڑ کر ساحل سمندر کے قریب قریب یثرب کی طرف روانہ ہوئے اور برابر ایک رات اور دوسرے دن کا
کچھ حصہ چلتے رہے.دوسرے دن دوپہر کے قریب جب سورج کی گرمی تیز ہوئی تو حضرت ابوبکر کے
عرض کرنے پر آپ ایک بڑے پتھر کے سایہ میں آرام فرمانے کے لیے اترے.حضرت ابو بکر نے آگے
بڑھ کر آپ کے واسطے جگہ تیار کی اور آپ ذرا لیٹ کر سو گئے اور حضرت ابوبکر ادھر اُدھر نظر دوڑا کر دیکھنے
لگے کہ کوئی تعاقب کرنے والا تو نہیں آ رہا.اتنے میں حضرت ابو بکر کو ایک چرواہا نظر آیا جس کے ساتھ
چند بکریاں تھیں جنہیں وہ اُسی پتھر کی طرف سایہ کی غرض سے لا رہا تھا.حضرت ابو بکر نے اس سے دودھ
کی اجازت لے کر اس کے ہاتھ اور بکری کے تھن خوب اچھی طرح صاف کروائے اور پھر اسے دودھ
دو ہنے کو کہا.چنانچہ اس نے ایک برتن میں دودھ دوہا اور پھر حضرت ابو بکر اُسے پانی میں ٹھنڈا کر کے آپ
کے پاس لائے.اس وقت تک آپ نیند سے جاگ چکے تھے؛ چنانچہ حضرت ابوبکر نے آپ کے سامنے
دودھ کا برتن پیش کیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا اور حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں کہ اس سے میری
طبیعت خوش ہو گئی.اس کے بعد حضرت ابوبکر نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ کوچ کا وقت ہو گیا
ہے آپ نے فرمایا.”ہاں چلو.چنانچہ آپ آگے روانہ ہو گئے لیکن ابھی آپ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ حضرت ابو بکڑ نے دیکھا کہ
ایک شخص گھوڑا دوڑائے ان کے پیچھے آرہا ہے.اس پر حضرت ابوبکر نے گھبرا کر کہا."یا رسول اللہ ! کوئی
شخص ہمارے تعاقب میں آرہا ہے.آپ نے فرمایا.” کوئی فکر نہ کرو.اللہ ہمارے ساتھ ہے.“
9
: بخاری باب الحجر ة عن براء بن عازب ے : خمیس وزرقانی سے : مسند احمد و ترمذی بحوالہ زرقانی
: ترندی و نسائی بحوالہ زرقانی کتاب المغازی ۵ : بخاری باب المهاجرین
Page 282
۲۶۷
یہ تعاقب کرنے والا سراقہ بن مالک تھا جو اپنے تعاقب کا قصہ خود اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے
کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے تو کفار قریش نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم ) یا ابوبکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے اس اس قد را انعام دیا جائے گا اور اس اعلان
کی انہوں نے اپنے پیغام رسانوں کے ذریعہ سے ہمیں بھی اطلاع دی.اس کے بعد ایک دن میں اپنی قوم
بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ قریش کے ان آدمیوں میں سے ایک شخص ہمارے پاس آیا اور
مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں نے ابھی ابھی ساحل سمندر کی سمت میں دور سے کچھ شکلیں دیکھی ہیں.میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور اس کے ساتھی ہوں گے.سراقہ کہتا ہے کہ میں فوراً
سمجھ گیا کہ یہ ضرور وہی ہوں گے مگر میں نے اُسے ٹالنے کے لیے (اور یہ فخر خود حاصل کرنے کی غرض سے )
کہا کہ یہ تو فلاں فلاں لوگ ہیں جو ابھی ہمارے سامنے سے گذرے ہیں.اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں
اس مجلس سے اٹھا اور اپنے گھر آ کر اپنی خادمہ سے کہا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے گھر کے پچھواڑے میں کھڑا کر
دے اور پھر میں نے ایک نیزہ لیا اور گھر کی پشت کی طرف سے ہو کر چپکے سے نکل گیا اور گھوڑے کو تیز کر
کے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں کے قریب پہنچ گیا.اس وقت میرے گھوڑے نے ٹھوکر
کھائی اور میں زمین پر گر گیا لیکن میں جلدی سے اُٹھا اور اپنا ترکش نکال کر میں نے ( ملک کے دستور کے
مطابق ) تیروں سے فال لی.فال میرے منشا کے خلاف نکلی مگر ( اسلام کی عداوت کا جوش اور انعام کا
لالچ تھا ) میں نے فال کی پروا نہ کی اور پھر سوار ہو کر تعاقب میں ہو لیا اور اس دفعہ اس قدر قریب پہنچ گیا
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ( جو اس وقت قرآن شریف کی تلاوت کرتے جارہے تھے ) قراءت کی
آواز مجھے سنائی دیتی تھی.اس وقت میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ بھی منہ
موڑ کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا.لیکن ابوبکر ( آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کی وجہ سے ) بار بار دیکھتے
تھے.میں جب ذرا آگے بڑھا تو میرے گھوڑے نے پھر ٹھوکر کھائی اور اس دفعہ اس کے پاؤں ریت کے
اندر جنس گئے اور میں پھر زمین پر آ رہا.میں نے اُٹھ کر گھوڑے کو جود دیکھا تو اس کے پاؤں زمین میں اس
قدر ھنس چکے تھے کہ وہ انہیں زمین سے نکال نہیں سکتا تھا.آخر بڑی مشکل سے وہ اٹھا اور اس کی اس کوشش
سے میرے ارد گر دسب غبار ہی غبار ہو گیا.اس وقت میں نے پھر فال لی اور پھر وہی فال نکلی.جس پر میں
نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صلح کی آواز دی.اس آواز
لے : شاخ بنو کنانہ
Page 283
۲۶۸
پر وہ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اُن کے پاس پہنچا.اس سرگذشت کی وجہ سے جو میرے
ساتھ گذری تھی میں نے یہ سمجھا کہ اس شخص کا ستارہ اقبال پر ہے اور یہ کہ بالآ خرآ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
غالب رہیں گے؛ چنانچہ میں نے صلح کے رنگ میں ان سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنے یا پکڑ
لانے کے لیے اس اس قدر انعام مقرر کر رکھا ہے اور لوگ آپ کے متعلق یہ یہ ارادہ رکھتے ہیں اور میں بھی
اسی ارادے سے آیا تھا مگر اب میں واپس جاتا ہوں.اس کے بعد میں نے انہیں کچھ زاد راہ پیش کیا مگر
انہوں نے نہیں لیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی اور سوال کیا.صرف اس قدر کہا کہ ہمارے متعلق کسی سے ذکر نہ
کرنا.اس کے بعد میں نے ( یہ یقین کرتے ہوئے کہ کسی دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک میں غلبہ
حاصل ہو کر رہے گا ) آپ سے عرض کیا کہ مجھے ایک امن کی تحریر لکھ دیں.جس پر آپ نے عامر بن فہیرہ کو
ارشاد فرمایا اور اُس نے مجھے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امن کی تحریرلکھ دی.اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آگے روانہ ہو گئے.جب سراقہ واپس لوٹنے لگا تو آپ نے اُسے فرمایا.سراقہ اُس وقت تیرا کیا حال ہو گا.جب
تیرے ہاتھوں میں کسری کے کنگن ہوں گے ؟ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ کسری بن ہرمز شہنشاہ
ایران ؟ آپ نے فرمایا ہاں.سراقہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں.کہاں عرب کے صحرا کا ایک بدوی
اور کہاں کسر کی شہنشاہ ایران کے کنگن ! مگر قدرت حق کا تماشا دیکھو کہ جب حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایران
فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو کسریٰ کے کنگن بھی غنیمت کے مال کے ساتھ
مدینہ میں آئے.حضرت عمرؓ نے سراقہ کو بلایا جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکا تھا اور اپنے سامنے اس کے
ہاتھوں میں کسری کے کنگن جو بیش قیمت جواہرات سے لدے ہوئے تھے پہنائے.سراقہ کے تعاقب سے رہائی ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے.راستہ میں زبیر بن
العوام سے ملاقات ہوگئی جو شام سے تجارت کر کے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکہ کو
واپس جارہے تھے.زبیر نے ایک جوڑا سفید کپڑوں کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک حضرت ابو بکر
کی نذر کیا اور کہا میں بھی مکہ سے ہو کر بہت جلد آپ سے مدینہ میں آملوں گا.اور بھی کئی لوگ راستہ
لے : یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایسے نازک اور بے سرو سامانی کے وقت میں بھی لکھنے کا سامان ساتھ ہوتا تھا.: بخاری باب الہجرت سے : یہ نظارہ غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت کشفی حالت میں دکھایا گیا ہوگا.: اسدالغابہ ذکر سراقہ
ه : بخاری باب الحجرت
Page 284
۲۶۹
میں ملتے تھے اور چونکہ حضرت ابو بکر" بوجہ تجارت پیشہ ہونے کے اس راستہ سے بار ہا آتے جاتے رہتے تھے
اس لئے اکثر لوگ ان کو پہچانتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے.لہذا وہ ابو بکر سے
پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے آگے آگے کون ہے.حضرت ابوبکر فرماتے ـ هذا يَهْدِينِيَ السَّبِيلَ - یہ میرا
ہادی ہے.وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی دلیل یعنی گائیڈ ہے جو راستہ دکھانے کے لئے حضرت ابو بکر نے
ساتھ لے لیا ہے مگر حضرت ابو بکر کا مطلب کچھ اور ہوتا تھا.اختتام سفر اور تکمیل ہجرت آٹھ روز کے سفر کے بعد راستہ میں مختلف جگہ ٹھہر تے ہوئے بارہ
ربیع الاول ۱۴ نبوی مطابق ۲۰ ستمبر ۶۲۲ ء کو آپ مدینہ کے پاس پہنچے ہے
اہل میٹرب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کے متعلق
خبر پہنچ چکی تھی اس لیے وہ ہر روز مدینہ
سے باہر آپ کے استقبال کے لیے آتے اور دیر دیر تک انتظار کرتے رہتے تھے مگر جب دھوپ تیز ہونے
لگتی تھی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے تھے.اُس دن بھی وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے
تھے مگر چونکہ دن بہت چڑھ آیا تھا اس لیے آج بھی مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے کہ اچانک جبکہ وہ
ابھی اپنے گھروں میں پہنچے ہی تھے ایک یہودی نے جو اپنی گڑھی میں ایک بلند مقام پر کسی اپنی غرض سے
کھڑا تھا دور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سفید لباس میں چمکتے ہوئے دیکھا اور
زور سے پکار کر کہا.”اے اہل عرب ! جس کا تم راہ دیکھتے ہو وہ یہ آتا ہے.‘ مخلص جماعت کے کان
،
میں یہ آواز پہنچی اور مسلمان خوشی کے جوش میں دیوانے ہو کر اُٹھ کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی ہتھیار
سنبھال کر دوڑتے بھاگتے ہوئے شہر سے باہر نکل آئے..: بخاری باب الحجرت
: زرقانی ومحمود پاشا مصری بعض محققین کی تحقیق کے مطابق آٹھ ربیع الاول تاریخ تھی.: عربوں میں ہتھیار لگا کر کسی کے استقبال کے لیے نکلنا اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ استقبال کرنے والا اپنے
مہمان کے لیے جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہے
Page 285
۲۷۰
مکی زندگی پر ایک سرسری نظر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے دور یعنی قبل از بعثت زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے جو
قلت واقعات کی شکایت ہم نے بیان کی تھی وہ آپ کی زندگی کے دوسرے دور میں بھی پوری طرح دور
نہیں ہوئی.یہ درست ہے کہ ماموریت کے دعوئی کے بعد ایسے لوگ موجود تھے جن کے واسطے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ کا حکم رکھتی تھی اور جو آپ کی تمام حرکات وسکنات کو غور کی نظر سے
مطالعہ کرتے تھے اور ہر وقت آپ کی صحبت میں رہنے کے خواہشمند تھے مگر جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں قریش
کے مظالم نے مکہ میں مسلمانوں کو کبھی بھی اکٹھا نہیں ہونے دیا اور کبھی بھی ان کو اتنی فرصت اور موقع نہیں
دیا کہ وہ اپنے آقا کی صحبت میں رہ کر اس کی زندگی کے تمام حالات کو آنے والی نسلوں کے لیے
بالتفصیل محفوظ کر دیں.باایں ہمہ بعثت سے قبل اور بعد کی زندگی کے حالات میں ایک بہت نمایاں فرق
نظر آتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ مدنی زندگی کے حالات میں یہ فرق بہت ہی نمایاں ہو جائے گا کیونکہ
مدینہ میں صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے کا
ہر وقت موقع ملتا تھا اور انہوں نے بھی جس تفصیل اور بسط کے ساتھ اس زمانہ کے متعلق آپ کے سوانح کو
ہم تک پہنچایا ہے وہ انہی کا حصہ ہے.دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں انبیاء گذرے ہوں گے مگر جس تفصیل
اور بسط کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تاریخ و حدیث میں محفوظ ہیں اس کا عشر عشیر بھی
کسی دوسرے نبی کے متعلق میسر نہیں.خدا ہزار ہزار رحمتیں نازل فرمائے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی
مقدس جماعت پر جس کے طفیل آج بھی جب کہ ساڑھے تیرہ سوسال کا عرصہ آپ کی وفات پر گذر چکا
ہے آپ کی جیتی جاگتی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور ہم اپنی زندگی کے ہر قدم پر آپ
کے پاک نمونہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.قیام مکہ اور سنین نبوی و ہجری
بعثت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قریباً تیرہ سال
ٹھہرے.بعض روایات میں دس سال بیان کئے گئے ہیں.یہ بھی
Page 286
۲۷۱
ایک لحاظ سے درست ہے کیونکہ ابتدائے وحی کے بعد آپ نے تین سال تک اپنے مشن کو مخفی رکھا تھا.پس اگر ان تین سالوں کو نکال دیں تو باقی دس سال ہی رہ جاتے ہیں.بہر حال یہ مسلم ہے کہ ہجرت کے
وقت آپ کی عمر ترپن سال کی تھی.ظہور اسلام سے پہلے قریش میں سنہ تاریخ عموماً عام الفیل کے حساب سے شمار ہوتا تھا؛ چنانچہ
مؤرخین بھی بعثت نبوی سے پہلے کے واقعات کی تاریخ بتانے کے لیے عموماً عام الفیل کا حوالہ دیتے ہیں
لیکن بعثت سے بعد کے واقعات کا سنہ بعثت نبوی سے شمار کیا جاتا ہے مگر یہ سنہ بھی صرف تیرہ سال یعنی
ہجرت تک چلتا ہے.اس کے بعد سے مستقل طور پر سنہ ہجری شروع ہوتا ہے.جس کی تجویز اور تعیین
ابتد ا حضرت عمرؓ کے عہد میں ہوئی تھی لے
یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ بعثت نبوی عام الفیل کے چالیسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی اور چونکہ
رمضان عربی مہینوں میں نواں مہینہ ہے اس لیے بعثت نبوی کا پہلا سال صرف چند ایام اور تین ماہ یعنی
بقیہ رمضان اور شوال.ذیقعد اور ذی الحجہ کا شمار ہوتا ہے اور چونکہ ہجرت نبوی ۱۴ نبوی ابتداء ماہ ربیع الاول
میں ہوئی تھی.اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از بعثت کی قیام در اصل صرف بارہ سال پانچ ماہ
اور چند ایام کا بنتا ہے.ہاں اگر رویا صالحہ کا زمانہ یعنی ابتدائی چند ماہ بھی زمانہ نبوت میں شمار کر لیے جاویں تو
یہ کل عرصہ قریباً تیرہ سال کا ہو جاتا ہے.نزول وحی کی کیفیت کلام الہی کے نزول کی کیفیت اور اس کے نزول کے وقت مُنزَل عَلَيْهِ کے
قلب کی حالت کو حقیقی طور پر سمجھنا تو صرف اسی شخص کا کام ہے جو اس کو چہ سے
آشنا ہو.تاہم جو اجمالی نقشہ قرآن شریف اور حدیث میں بیان ہوا ہے.وہ درج ذیل کیا جاتا ہے:
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُعَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمُ :
یعنی ” نہیں کلام کرتا اللہ کسی بندے سے مگر وحی کے طریق پر یا کسی پردے کے پیچھے سے یا
کوئی فرشتہ بھیجتا ہے جو القا کرتا ہے بندہ پر اللہ کے اذن سے.بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور
حکمت والا ہے.“
: طبری
: طبری
۳ : سورۃ شوری: ۵۲
Page 287
۲۷۲
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کے تین طریق بتائے ہیں:
اول.وحی یعنی براہ راست لفظی کلام جس کی دوصورتیں ہو سکتی ہیں :
(الف) یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الفاظ براہ راست انسان کے کانوں میں پہنچیں.وحی کی یہ صورت عموماً سب سے زیادہ بارعب اور شاندار ہوتی ہے.(ب) یہ کہ اس کی زبان
پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الفاظ جاری کیے جائیں.ان دونوں
طریقوں کو اسلامی اصطلاح میں وحی کہتے ہیں.دوسرے.مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ یعنی کسی تحریر کے سامنے آجانے یا کشف یا خواب یا قلبی القا
وغیرہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر بندہ پر ظاہر ہو.تیرے يُرْسِلَ رَسُولًا - یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ وغیرہ بندہ کے پاس آوے اور خدا
کی طرف سے اس کے ساتھ کلام کرے.اسی کے مطابق حدیث میں حضرت عائشہؓ کی روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ:
أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّى وَقَدْ
وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَ اَحْيَانًا يَتَمَثَلُ لِىَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَاعِيَ مَا يَقُولُ
یعنی " کبھی تو میرے پاس وحی آتی ہے گھنٹی کی چھنکار کی طرح ( تا کہ ٹیلیفون کی طرح پہلے
الارم بجا کر ہوشیار اور متوجہ کیا جائے ) اور یہ طرز وحی کی (بوجہ خدائی کلام کی براہ راست حامل
ہونے کے ) مجھ پر سخت ترین ہوتی ہے.پھر بعد اس کے کہ میں اس کا کلام خوب
محفوظ کر چکا ہوتا
ہوں یہ آواز مجھ سے جدا ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی فرشتہ میرے پاس انسان کی صورت اختیار
کر کے آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے سو میں اس کی بات کو بھی محفوظ کر لیتا ہوں.“
اس حدیث میں مِن وَرَائِي حِجَاب والی صورت نہیں بیان کی گئی.جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت جو
رویا وغیرہ سے تعلق رکھتی ہے ایک نسبتاً عام صورت ہے اور اکثر لوگ علی قدر مراتب اس کی حقیقت سے واقف
ہوتے ہیں بمقابلہ باقی دوصورتوں کے جن کا حلقہ صرف رسولوں اور خاص خاص لوگوں تک محدود ہوتا ہے.مذکورہ بالا حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام الہی کی بڑی اقسام تین ہیں مگر یہ کہ یہ تینوں قسمیں پھر
: بخاری کتاب بدء الوحی
Page 288
۲۷۳
آگے بہت سی ماتحت اقسام میں منقسم ہیں جن کا موٹا نقشہ حسب ذیل صورت میں سمجھا جاسکتا ہے.اول: کلام بصورت وحی یعنی براہ راست لفظی کلام.جس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں.(الف) کلام الہی کا براہ راست انسانی کانوں تک پہنچنا جوکئی طریق پر ہوسکتا ہے.(ب) خدائی تصرف کے ماتحت خود انسان کی زبان پر کوئی کلام جاری ہونا.یہ ہر دو صورتیں
یقہ اور نوم ہر دو حالتوں میں ممکن ہیں.دوم کلام بواسطه ارسال رسل یعنی خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ وغیرہ انسان کے سامنے نمودار ہوکر
اس کے ساتھ خدائی منشاء کے ماتحت کلام کرے.یہ بھی کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے اور یقظہ اور نوم ہر دو
حالتوں میں ممکن ہے.سوم کلام پس پردہ یعنی نہ تو خدا کا براہ راست کلام ہو اور نہ ہی کسی فرشتہ کا براہ راست واسطه
اختیار کیا جائے بلکہ اللہ تعالی کسی پردے کے پیچھے رہ کر کسی رنگ میں اپنے منشاء کا اظہار فرماوے.اس کی
کئی صورتیں ہوسکتی ہیں.مثلاً
(الف) کشف یعنی عین بیداری یا نیم بیداری میں خدائی تصرف کے ماتحت کوئی نقشہ دکھایا جانا.خواہ وہ
نقشہ اصل حالت کا مظہر ہو یا قابل تعبیر ہو.یہ حالت یقظہ کی صورت میں ہوتی ہے.اور حواس ظاہری کے
تعطل اور عدم تعطل ہر دو حالتوں میں ممکن ہے یعنی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری حواس بھی کام کر رہے
ہوتے ہیں اور اسی حالت میں باطنی حواس میں ایک بیداری پیدا ہو کر کوئی نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا
ہے اور بعض اوقات ایک آن واحد کے لیے ظاہری حواس معطل ہو کر حواس باطنی کو جگہ دے دیتے ہیں.(ب) رؤیا یا خواب جس کی کیفیت سے اکثر لوگ واقف ہیں جو نیند کی حالت میں دکھائی جاتی ہے اور
بالعموم تعبیر طلب ہوتی ہے.(ج) کسی تحریر کا آنکھوں کے سامنے پھر جانا جو یقظہ اور نوم ہر دو حالتوں میں ممکن ہے.مندرجہ بالا صورتوں کے علاوہ ایک وحی خفی بھی ہوتی ہے یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات
انسان کے دل میں ڈالا جا نا مگر اس کا پہچاننا خاص مشق چاہتا ہے.یہ صرف ایک موٹا اور سرسری نقشہ ہے ورنہ در حقیقت کلام الہی کی صورتیں بہت ہیں اور بسا اوقات
ایک سے زیادہ قسمیں ایک ہی وقت میں جمع بھی ہو جاتی ہیں یا
ا : اس بارے میں متقدمین کے خیالات معلوم کرنے ہوں تو زرقانی جلد ا باب مراتب الوحی دیکھئے.
Page 289
۲۷۴
نزول وحی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوتی تھی اس کے متعلق حضرت عائشہ
فرماتی ہیں کہ :
لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِى الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ
جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا
دو یعنی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات سخت سردی کا دن ہوتا تھا لیکن جب آپ پر وحی
اترتی تھی تو پسینہ آپ کی پیشانی سے پھوٹ پھوٹ کر بہتا تھا.“
پھر زید بن ثابت جو آپ کے کاتب وحی تھے روایت کرتے ہیں کہ :
أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي
فَتَقْلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ اَنْ تَرُضٌ فَخِذِى ثُمَّ سُرِّئَ عَنْهُ
د یعنی ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی کہ آپ پر وحی کی
حالت طاری ہوئی اس وقت آپ کی ران مجھے اس قدر بوجھل محسوس ہوتی تھی کہ میں ڈر گیا کہ
کہیں میری ران بوجھ سے ٹوٹ نہ جاوے.پھر اس کے بعد آپ کی یہ حالت جاتی رہی.“
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے نزول کے وقت چونکہ روحانی حسیں بیدار ہو کر بہت تیز ہو جاتی ہیں.اس لیے عموماً انسان کی جسمانی طاقت معطل ہو جاتی ہے اور جسم مردہ کی طرح بے سہارا ہو کر گر جاتا ہے.اس جگہ اس شبہ کا ازالہ بھی ضروری ہے جو بعض ناواقف اور سادہ مزاج لوگوں کے دل میں پیدا ہوا
کرتا ہے کہ خدا بولتا کس طرح ہے؟ یعنی کیا خدا کی کوئی زبان ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے؟ اس کے متعلق
یا درکھنا چاہیئے کہ ہر ہستی کے حالات اور صفات کے مطابق اس کی طاقتوں کا اظہار ہوا کرتا ہے.اللہ تعالیٰ
کی ہستی چونکہ نہایت لطیف اور غیر مادی اور غیر محدود اور وراء الوراء ہستی ہے اس لیے انسان کے حالات پر
جو مادی بھی ہے اور مخلوق بھی اور محدود بھی اس کا قیاس ہرگز نہیں ہوسکتا.پس یہ ایک انتہائی درجہ جہالت
کا خیال ہو گا اگر یہ سمجھا جاوے کہ چونکہ انسان کو کلام کرنے کے لیے ایک گوشت کے لوتھڑے کی ضرورت ہے
اس لیے خدا کی بھی کوئی ایسی زبان ہونی چاہیئے.حقیقت یہ ہے کہ جس طرح خدا اپنی دوسری لا تعداد
طاقتوں کو کام میں لاتا ہے.اسی طرح وہ بولتا بھی ہے مگر بغیر ظاہری زبان کے اور سنتا بھی ہے مگر بغیر ظاہری
کانوں کے اور دیکھتا بھی ہے مگر بغیر ظاہری آنکھوں کے.بے شک اس کی ہستی کو محسوس کرنا انسانی عقل
: بخاری کتاب التفسیر
بخاری
Page 290
۲۷۵
سے بالا نہیں مگر اس کی ہستی کی گنہ کو سمجھنا یقینا عقل انسانی سے بالا و برتر ہے.ایک گراموفون کو ہی دیکھو.کیا انسان کی طرح اس کی بھی کوئی زبان ہے جس سے وہ بولتا ہے؟ پس جب مخلوق اور ادنی چیزوں میں
اس قدر اختلاف موجود ہے تو خدا جیسی خالق و مالک ، اول و آخر ، از لی وابدی ،لطیف و غیر محدود قادر مطلق
ہستی کو انسان پر قیاس کرنا کس قدر جہالت کا فعل ہوگا.جمع قرآن جمع قرآن کے متعلق اصل بحث تو کتاب کے حصہ دوم میں آئے گی مگر اس جگہ ایک مختصر
نوٹ میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف جو ہم مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور
جسے ہم اللہ کا کلام سمجھتے ہیں جو اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ا تا را یکلخت نازل نہیں ہوا بلکہ
آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہوا تھا اور اس تدریجی نزول میں کئی حکمتیں ہیں.جن کے بیان کی اس
جگہ ضرورت نہیں جو سورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی سورتیں
کہلاتی ہیں اور بعد کی مدنی.قرآن شریف کا جو جو حصہ نازل ہوتا جاتا تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کو سنا دیتے تھے اور بعض کو یاد کر وا دیتے تھے اور اس کے مختلف نسخے لکھوا بھی دیتے تھے.جس کے لیے
آپ نے اپنے خواندہ صحابیوں میں سے متعدد کاتب وحی مقرر کیے ہوئے تھے ، چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ
جب زمانہ جاہلیت میں حضرت عمرؓ غصہ کی حالت میں اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ان کے
پاس لکھا ہوا قرآن شریف موجود تھا جس پر سے خباب بن الارت تلاوت کر کے حضرت عمر کی بہن اور
بہنوئی کو سنا ر ہے تھے.قرآنی سورتیں قرآن شریف میں اسی ترتیب سے نہیں رکھی گئیں جس ترتیب سے ان کا نزول ہوا بلکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الہی حکم کے ماتحت اُن کی ایک خاص ترتیب مقرر فرما دی.چنانچہ ہر سورۃ
کے ختم ہونے پر آپ ہدایت فرماتے تھے کہ اسے فلاں موقع پر رکھو.اسی طرح ہر آیت کے نزول پر بھی خود
فرماتے تھے کہ اسے فلاں سورۃ میں فلاں جگہ ڈالو یا جو ترتیب قرآنی آیات اور سورتوں کی آپ نے
خدائی تفہیم کے ماتحت مقرر فرمائی وہی اب تک موجود ہے اور غور و تدبر کرنے والوں پر اس ترتیب کی خوبی
مخفی نہیں رہ سکتی.مکی سورتیں چونکہ مکہ میں نزول شریعت کی ابتدا تھی اس لیے زیادہ تر عقائد کی اصولی باتوں پر ہی
اکتفا کی گئی ہے.ویسے بھی چونکہ مکہ میں صرف مشرکین اور بت پرست بستے تھے اس
لے : ابوداؤ د ترندی و مسند احمد بحوالہ مشکوة کتاب فضائل القرآن وفتح الباری جلد ۹ صفحه ۱۹-۲۰
Page 291
لیے مکی آیات میں زیادہ تر شرک اور بت پرستی ہی کی تردید کی گئی ہے اور ہستی باری تعالیٰ اور توحید کے
دلائل بیان کئے گئے ہیں.اس کے بعد سلسلہ رسالت کی حقانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت کا ثبوت اور اس پر کفار کے اعتراضوں کے جوابات اور گذشتہ انبیاء کے حالات مذکور ہیں.پھر
ملائکہ کے وجود، قیامت، جزا سزا، جنت و دوزخ ، تقدیر وغیرہ کے مسائل پر دلچسپ بحثیں ہیں.اس کے
علاوہ جاہلانہ رسوم اور بدعات سے روکا گیا ہے اور نیک عادات واخلاق حسنہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے
اور پھر اس سے اعلیٰ مقام یعنی عرفان الہی کی راہوں
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے طریقوں کی
طرف راہنمائی کی گئی ہے.عبادات میں مکی سورتیں سوائے نماز کے حکم کے باقی سب احکام سے خالی ہیں؛ چنانچہ حج ، روزہ، زکوۃ
کا کہیں ذکر نہیں آتا، کیونکہ یہ سب مدینہ میں فرض ہوئے تھے.جہاد بالسیف کا ذکر بھی مکی آیات میں نہیں
ملتا کیونکہ مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو کا حکم تھا اور کفار پر اتمام حجت کیا جا رہا تھا.پھر جب
اتمام حجت ہو چکا اور کفار اپنے مظالم سے باز نہ آئے بلکہ دن بدن ترقی کرتے گئے.حتی کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑا اور پھر ہجرت کے بعد بھی قریش نے
مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑ ا تب جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد بالسیف کی اجازت نازل ہوئی.اسی طرح چونکہ مکہ میں اسلامی سوسائٹی کی بالکل ابتدائی حالت تھی بلکہ حق تو یہ ہے کہ مکہ میں کوئی
اسلامی سوسائٹی تھی ہی نہیں کیونکہ قریش کے بے دردانہ مظالم نے سب کو منتشر کر رکھا تھا اس لیے مکی
سورتوں میں تمدنی احکام بھی نظر نہیں آتے.اسی طرح سیاسی احکام بھی مکی سورتوں میں مفقود ہیں.گویا
فقہی مسائل سے مکی سورتیں قریباً قریباً خالی ہیں.یہی وجہ ہے کہ مکی سورتیں عام طور پر بہت چھوٹی ہیں
اور ان کی زبان بھی زیادہ زور دار ، جوش والی اور موزوں ہے بمقابلہ مدنی سورتوں کے جن میں احکام
کی کثرت اور فقہی مسائل کی پیچیدگیوں کی وجہ سے طرز بیان میں مناسب تبدیلی آگئی ہے اور یہ تبدیلی
نہایت موزوں اور بر محل ہے کیونکہ بلاغت اسی میں ہے کہ طرز کلام واقعات کے مناسب حال ہو.مسئلہ ارتقا یعنی درجہ بدرجہ ترقی کرنا ایک مسلم مسئلہ ہے اور گو اس کی وہ صورت جو اہل مغرب
ارتقاء نبوی
پیش کرتے ہیں درست نہ ہو مگر جہاں تک اصول کا تعلق ہے اس میں شبہ نہیں کہ
دن بدن اس کی حقانیت پر زیادہ سے زیادہ روشنی پڑتی جارہی ہے.درحقیقت اللہ تعالیٰ نے خود اس مسئلہ کو
قرآن شریف میں متعدد موقعوں پر بیان کیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور انسانی پیدائش کے بیان
Page 292
۲۷۷
میں تو خلق آدم کے ارتقائی مراحل بھی صراحت کے ساتھ بیان کئے ہیں.دراصل اللہ تعالیٰ کے تمام
کاموں میں تدریجی ترقی کا اصول نمایاں طور پر کام کرتا نظر آتا ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہی اصول انبیاء
علیہم السلام کے حالات زندگی میں پایا جاتا ہے.جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ انبیاء کا وجود کسی فوری
انقلاب
کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بالکل غلط سمجھا ہے اور اس نے نبوت کی حقیقت پر بالکل غور نہیں کیا کیونکہ جس طرح
صحیفہ قدرت پر ہراک چیز تدریجا بنتی ہے اسی طرح انبیاء بھی اپنی نبوت میں تدریجا نشو ونما پاتے ہیں اور
قطعاً کسی فوری انقلاب کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ آہستہ آہستہ کئی درمیانی حالتوں میں سے گذرنے کے بعد
اُس آخری مقام کو حاصل کرتے ہیں جس پر ان کے مراتب سلوک ختم ہوتے ہیں.تمام انبیاء جس طرح
جسمانی لحاظ سے مراحل خلق میں سے گذرتے ہوئے پیدا ہوئے پھر انہوں نے اپنے بچپن کے دن
گزارے.پھر وہ نوجوان ہوئے اور پھر اپنی پختگی کو پہنچے.اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی وہ پہلے
پیدا ہوتے ہیں اور پھر درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اپنی پختگی کو پہنچتے ہیں اور پھر مقام نبوت میں بھی وہ ایک
جگہ نہیں ٹھہرتے بلکہ دن بدن شاہراہ ترقی پر آگے قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں.یہ تدریجی نشو ونما
قانون فطرت کے عین مطابق ہے اور فوری انقلاب کے بداثرات سے محفوظ رکھتا ہے نیز اور بھی کئی طرح
سے مفید بلکہ ضروری ہوتا ہے مگر اس جگہ اس مسئلہ کی تفصیلات کی گنجائش نہیں اس جگہ ہمیں مختصر طور پر صرف
یہ بتانا مقصود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں یہ تدریجی نشو و نما کس طریق پر کام
کرتا نظر آتا ہے.سو اختصار کی غرض سے ہم آپ کی ابتدائی زندگی سے قطع نظر کر کے صرف دعوئی اور
اس کے مقدمات سے آپ کی زندگی کا مطالعہ شروع کرتے ہیں.سب سے اول ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش حق میں ترک دنیا کا طریق اختیار
کیا اور خلوت میں رہنا شروع کیا.اس پر ایک عرصہ گذرا تو آپ پر رویا صادقہ کا دروازہ کھولا گیا اور آپ
کو سچے خواب آنے شروع ہوئے جو اپنے وقت پر پورے ہو ہو کر آپ کی پختگی کا موجب ہوتے رہے اور
یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا.جب آپ اس کوچے سے ایک حد تک آشنا ہو گئے اور طبیعت نبوت کے
مناسب حال پختگی کو پہنچ گئی تو غار حرا میں آپ کے پاس الہی فرشتہ آیا اور اُس نے اللہ کی طرف سے آپ
کے ساتھ کلام کیا اور رویا صادقہ سے اوپر کا مقام آپ پر کھولا گیا لیکن باوجود اس کے کہ آپ اس کو چہ سے
آشنا ہو چکے تھے آپ کی طبیعت اس تبدیلی کو پہلی دفعہ پوری طرح برداشت نہیں کر سکی اور آپ سخت خوفزدہ
سوره مومنون : ۱۲ تا ۱۵
Page 293
۲۷۸
ہو گئے اور یہ خوف واضطراب آپ کو ایک عرصہ تک تکلیف دیتا رہا.حتی کہ اس ربانی رسول کے بار بار
آپ کے پاس آنے اور آپ کو تسلی دینے کے بعد آپ کو پورا پورا سکون حاصل ہوا.اس اطمینان کے بعد آپ نے اپنا کام شروع فرمایا مگر اس میں بھی تدریجی ترقی کا پہلو موجود تھا.پہلے پہل آپ نے عام تبلیغ شروع نہیں کی بلکہ صرف اپنے دوستوں اور عزیزوں تک تبلیغ کا کام محدود رکھا
اور اڑھائی تین سال تک صرف خفیہ طور پر فرض تبلیغ ادا فرماتے رہے اس کے بعد آپ نے الہی حکم کے تحت
کھلی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا مگر اس زمانہ میں بھی آپ کے کام کا دائرہ عموماً مکہ والوں تک محدود رہا.بے شک باہر سے آنے والوں کے لیے بھی پیغام حق کا دروازہ کھلا تھا اور مسیح ناصری کی طرح متلاشیان حق
سے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ ”میں بچوں کا کھانا کتوں کے آگے کیونکر ڈال دوں.مگر اوائل میں آپ کا
اصل روئے سخن قریش مکہ کی طرف تھا اور وہی اصل زیر تبلیغ تھے اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا لیکن جب
مکہ والوں نے نہ صرف انکار پر اصرار کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو سخت سے سخت
مظالم کا تختہ مشق بنایا بلکہ اس بات کا بھی عہد کر لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے اور عملاً
اپنے اوپر تبلیغ اسلام کا دروازہ بند کر لیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی توجہ مکہ والوں سے ہٹا کر
دیگر قبائل عرب کی طرف پھیر لی.طائف کا سفر اسی تبدیلی کا نتیجہ تھا.یہی وجہ ہے کہ اس زمانہ میں قریش
مکہ میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم نظر آتی ہے اور ان کی جگہ دیگر قبائل عرب میں اسلام
زیادہ پھیلتا نظر آتا ہے.یثرب کے قبائل اوس اور خزرج اس کی ایک نمایاں مثال ہیں.ہجرت کے بعد
یہود اور نصاریٰ کے ساتھ معاملہ پڑا اور زینہ تبلیغ کی آخری سیڑھی اس وقت ختم ہوئی جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے سلاطین عجم کے نام تبلیغی مراسلات بھیجے اور اسود واحم کو پیغام شروع ہوا.اپنے مقام کے متعلق بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً انکشاف ہوا چنا نچہ شروع شروع میں تو
آپ کی وحی میں آپ کے متعلق نبی اور رسول کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا.صرف ایک عمومی رنگ میں تبلیغ
حق کا حکم تھا اور جب نبوت اور رسالت کے مقام کا اظہار ہوا تو اس کے بعد بھی آپ ایک عرصہ تک اپنے
آپ کو صرف یکے از انبیاء خیال فرماتے رہے اور بس.اپنی فضیلت اور ختم نبوت کے متعلق قطعا کوئی دعویٰ
نہ تھا بلکہ ہجرت کے بعد تک یہ حال تھا کہ اگر کوئی صحابی اپنے جوش عقیدت میں آپ کو دیگر انبیاء پر افضل
قرار دیتا تھا تو آپ اسے سختی کے ساتھ روک دیتے تھے ، چنانچہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ مدینہ میں ایک
دفعہ ایک صحابی نے ایک یہودی کے سامنے حضرت موسی " پر آپ کی فضیلت بیان کی تو آپ اس صحابی پر
Page 294
۲۷۹
بہت ناراض ہوئے اور حضرت موسی کی ایک فضیلت بیان کر کے اس یہودی کی دلداری فرمائی یا لیکن
پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے خود فر مایا کہ:
لَوْ كَانَ مُوسَىٰ وَعِيْسَىٰ حَيَّيْنِ لَمَا وَسِعَهُمَا إِلَّا اتَّبَاعِي
د یعنی اگر اس وقت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام زندہ ہوتے تو اُن کو بھی بجز میری پیروی کے
چارہ نہ تھا.“
پھرا اوائل میں جب کسی صحابی نے آپ کو خیر البریہ یعنی افضل الخلق کہہ کر پکارا تو آپ نے اُسے روکا
اور فرمایا ذَالِكَ إِبْرَاهِیم، یعنی افضل الخلق تو ابراہیم تھے.نیز فرمایا ” مجھے یونس بن مٹی پر فضلیت
لیکن پھر خود فر مایا کہ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ - یعنی میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں
مت دو."
مگر اس وجہ سے میں اپنے اندر کوئی تکبر نہیں پاتا.یہ گویا ارتقاء علمی تھا کیونکہ آپ افضل الرسل اور سید ولد
آدم تو اوائل سے ہی تھے مگر اس کا انکشاف آپ پر آہستہ آہستہ ہوا اور یہ بھی درست ہے کہ آپ کے
مدارج میں بھی آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی تھی.کی زندگی میں اشاعت اسلام بعثت کے بعد جوقریباً تیرہ سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مکہ میں گذارے اُن میں اسلام سرزمین عرب میں گو جڑ پکڑ چکا
تھا اور قریش مکہ سے باہر بھی اس کا اثر پہنچ چکا تھا؛ چنانچہ ابوذر غفاری، عبداللہ بن مسعود ھذیلی ، ضماد بن
تقلبه از دی ، ابو موسی اشعری طفیل بن عمرو دوسی ، سعد بن معاذ اوسی ، سعد بن عبادہ خزرجی وغیرہ کئی غیر قبائل
کی مثالیں موجود ہیں جو اس زمانہ میں اسلام لائے ، مگر اس میں شک نہیں کہ ابھی تک اسلام ایک نہایت
کمزور حالت میں تھا اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے ان مخالف عناصر کے مقابلہ میں جن کا اسے سامنا تھا
اس کی زندگی خطرہ سے باہر نہیں تھی.قریش مکہ میں سے ہجرت نبوی تک اسلام لانے والوں کی تعداد صحیح طور پر معلوم نہیں ہے اور نہ کسی
روایت میں بیان ہوئی ہے لیکن قرائن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قریش اور ان کے متعلقین میں سے
ہجرت تک مسلمان ہونے والوں کی تعداد تین سونفوس سے کسی صورت میں زیادہ نہیں ہوگی.اس تعداد میں
: بخاری کتاب بدء الخَلَقَ بَابِ وَإِنَّ يُوْنَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
: تفسیر ابن کثیر جلد ۲ صفحه ۲۴۶ زیر آیت وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
: مسند احمد جلدا
: بخاری کتاب بدء الخلق
۵: ترمذی وابن ماجه
Page 295
۲۸۰
عورتیں اور بچے سب شامل ہیں.گویا قریش مکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ کوششوں کا نتیجہ
یہی تین سو جانیں تھیں اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان میں سے کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جو اپنی کم سنی یا مفلسی
یا کسی اور وجہ سے قریش میں کوئی اثر ورسوخ نہیں رکھتے تھے.قریش کے علاوہ دیگر قبائل عرب میں سے مسلمان ہونے والوں کی تعداد اہل میثرب کو الگ رکھتے
ہوئے بہت ہی کم نظر آتی ہے.ہاں یثرب میں البتہ جلد جلد اسلام پھیلا اور قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہجرت
نبوی سے پہلے مدینہ والوں میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد بشمولیت زن و فرزندکئی سو تک ضرور پہنچ چکی ہوگی.اس طرح گویا ہجرت تک کل مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ قریباً ایک ہزار بنتی ہے.جن میں اگر
عورتوں اور بچوں کو الگ الگ رکھیں تو بالغ مرد شاید تین چار سو ہوں گے لیکن یہ بھی ہجرت کے بعد سب کے
سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں موجود نہیں تھے بلکہ کچھ متفرق طور پر اپنے اپنے قبائل
میں تھے.کچھ حبشہ میں تھے اور کچھ ہجرت کی طاقت نہ رکھنے والے ابھی تک مکہ میں ہی قریش کے مظالم
کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے.اس قلیل نفری کے ساتھ اسلام مذاہب عالم کی جولانگاہ میں بازی لے جانے
کا دعوی بھرتا ہوا قدم زن ہورہا تھا.قریش کی ایذا رسانیوں کا اثر مسلمانوں پر قریش کے مظالم کی مختصر کیفیت اوپر بیان ہو چکی
ہے.ان مصائب پر مسلمانوں نے صبر اور
برداشت کا جو اعلیٰ نمونہ دکھایا وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے.صحیح روایات سے ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی
شخص نے ان مصائب سے ڈر کر ارتداد کی راہ اختیار کی ہو.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں
بلا شبہ ہم کو بعض مرتدین نظر آتے ہیں اور دراصل ارتداد کا سلسلہ ایک حد تک ہر نبی کے زمانہ میں پایا جاتا
ہے لیکن آپ کی مکی زندگی میں محض مصائب کے ڈر کی وجہ سے کسی مسلمان کے حقیقی ارتداد کا ذکر کم از کم
مجھے کسی صحیح روایت میں نہیں ملا.اس کی یہ وجہ تھی کہ چونکہ قریش کے یہ مظالم بر ملا ہوتے تھے اور ہر شخص
مسلمانوں کے مصائب و آلام سے آگاہ تھا اس لئے اس زمانہ میں جو بھی ایمان لاتا تھا وہ اس بات کے
فیصلہ کے بعد اسلام لاتا تھا کہ مجھے حق کی راہ میں جتنی بھی تکالیف سہنی پڑیں وہ میں برداشت کروں گا.اس
لیے مسلمان ہونے کے بعد یہ مصائب کسی شخص کو اسلام سے پھیر نہیں سکتے تھے مگر وقتی طور پر ان مصائب کا
ایک ضرر رساں اثر ضرور تھا اور وہ یہ کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان مصائب کی وجہ سے اسلام لانے کی
جرات نہیں کر سکتے تھے.ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کا اثر پہنچتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ شرک و بت پرستی
Page 296
۲۸۱
کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آجائیں مگر ان مصائب کے طوفان کے سامنے ایمان کی
چنگاری ان کے قلوب میں چمک چمک کر بجھ بجھ جاتی تھی.پھر بہتیرے ایسے بھی تھے جن کو ان مصائب کے
منظر نے اسلام کی طرف توجہ کرنے سے ہی روک رکھا تھا.علاوہ ازیں قریش کے مظالم کا ایک یہ بھی اثر تھا کہ
مسلمان پوری طرح اپنے عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے اور چونکہ جتنی تبلیغ زیادہ ہو اسی نسبت سے پیغام حق
زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور پھر اسی نسبت سے ماننے والے بھی زیادہ نکل آتے ہیں.اس لیے بھی مکہ
میں مسلمانوں کی تعداد جلد جلد ترقی نہیں کرسکی.مسلمان ان رکاوٹوں کو محسوس کرتے تھے اور دل ہی دل
میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتے تھے.ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن بن عوف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ "یا رسول اللہ ! جب ہم مشرک تھے تو ہم معزز تھے اور کوئی شخص
ہماری طرف آنکھ تک نہیں اٹھا سکتا تھا.لیکن مسلمان ہو کر ہم کمزورونا تو اں ہو گئے ہیں اور ہمیں ذلیل ہو کر
رہنا پڑتا ہے.پس آپ ہمیں ظالموں کے مقابلہ کی اجازت دیں.آپ نے فرمایا:
إِنِّي أُمِرْتُ بِالْعَفْوِ فَلَا تُقَاتِلُوا
مجھے ابھی تک عضو کا حکم ہے.اس لیے میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا.“
اپنے آقا کے اس حکم پر مسلمانوں نے ہاں انہی شیر دل مسلمانوں نے جنہوں نے اس کے چند سال
بعد قیصر و کسریٰ کے تخت اُلٹ کر رکھ دیئے جس صبر ورضا کے ساتھ ان مظالم کو برداشت کیا اس کی کسی قدر
تفصیل اوپر گذر چکی ہے.کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مکہ میں مسلمانوں کا کفار کے مقابلہ میں تلوار نہ
اٹھانا اور خاموشی اور صبر کے ساتھ ان مظالم کو برداشت کرنا اس وجہ سے نہیں تھا جیسا کہ بعض مخالفین نے سمجھا
ہے کہ وہ کمزور تھے اور مقابلہ کی طاقت نہ رکھتے تھے بلکہ اس لیے تھا کہ ابھی تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو عفو کا حکم تھا اور صحابہ کو مقابلہ کی اجازت نہیں تھی لیکن جب اتمام حجت ہو چکا اور کفار اپنے مظالم سے
باز نہ آئے بلکہ دن بدن زیادہ شوخ اور زیادہ متمرد ہوتے گئے اور انہوں نے اسلام کے پودے کو جڑ سے
اکھیڑ پھینکنے کی ٹھان لی اور ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا تو باوجود اس کے کہ اس وقت بھی
آپ کے پاس عرب کے مقابلہ کے لیے قطعا کوئی جمعیت نہ تھی آپ نے وہی مٹھی بھر جماعت لے کر ان کا
مقابلہ کیا اور چونکہ اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال تھی آپ اس مقابلہ میں کامیاب ہوئے.ے نسائی
Page 297
۲۸۲
ہجرت نبوی اور اس کی علت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ہجرت کوئی خوشی
کا سفر نہ تھا جو سیر و سیاحت کی غرض سے کیا گیا ہو بلکہ یہ سفرقریش کے
ان بیدر دانہ مظالم کا نتیجہ تھا جن کا مسلمان سالہا سال سے تختہ مشق بنے ہوئے تھے.حتی کہ آخر تنگ آ کر
مسلمانوں اور ان کے محبوب آقا کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا.جو جو مظالم ان ابتدائی تیرہ سالوں میں
مسلمانوں نے قریش مکہ اور ان کے ہم خیالوں کے ہاتھوں برداشت کئے ان کا صحیح صحیح اندازہ کرنا محال
ہے.صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ عرب جیسے جاہل اور آزاد ملک میں قریش جیسی وحشی اور متکبر قوم اپنی
عداوت کے جوش و خروش میں جو جو مظالم کمزور و بے بس مسلمانوں پر کر سکتی تھی وہ سب اس نے کئے.مسلمانوں کی تذلیل کے لیے ان پر ہنسی اور مذاق اڑایا گیا.ان کے خلاف دلآ زار طعن و تشنیع اور گندی گالی
گلوچ سے کام لیا گیا.ان کو خدا کی عبادت سے روکا گیا اور توحید کے اعلان سے جبرا منع کیا گیا.ان کو اُن
کے پیارے اور محبوب آقا سے الگ کر دینے کی کوشش کی گئی.اُن کو نہایت بے دردانہ طور پر مارا اور پیٹا
گیا.ان میں سے بعض کو نہایت وحشیانہ طور پر قتل کیا گیا.ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی.ان
کا بائیکاٹ
کر کے اُن کو بھوک اور پیاس سے ہلاک کرنے کی ٹھانی گئی.ان کے مال و متاع چھین لیے گئے.حتی کہ
ان کو اپنے وطن سے نکل کر بھاگنا پڑا اور جو ٹھہرے وہ سینے پر پتھر رکھ کر ٹھہرے.پھر ان کے آقا اور سردار کو
جو انہیں اُن کی جانوں سے زیادہ عزیز تھا سخت سے سخت دکھ دیئے گئے اور بر ملا بدنی تکالیف پہنچائی گئیں اور
اس پر پتھر برسائے گئے حتی کہ اس کا بدن خون سے تر بتر ہو گیا اور آخر اس کے قتل کا منصوبہ کیا گیا اور منصوبہ
بھی ایسا کہ جس میں سب قبائل قریش شریک تھے اور ہر قبیلہ اس کے مقدس خون سے اپنے ناپاک ہاتھ
رنگنے کے واسطے تیار ہو گیا اور اسلام کے پودہ کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی ٹھان لی گئی.تو کیا ان مظالم کے نتیجہ
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی ہجرت کوئی معمولی سفر تھا کہ یونہی رائیگاں جاتا اور
خدائے غیور کی غیرت جوش میں نہ آتی ؟ نہیں بلکہ ہجرت میں خدا کی طرف سے یہ صاف اشارہ تھا کہ
اب قریش کے مظالم کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ظالم اپنی کیفر کردار کو پہنچے.
Page 298
۲۸۳
خاتمہ
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِللَّهِ كه کا پہلا حصہ ختم
ہوا.خاکسار راقم الحروف خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجالا تا ہے کہ اُس نے اپنے
فضل و کرم سے مجھے اس کے پورا کرنے کی توفیق دی.اب اسے اللہ تو اپنے فضل
سے ایسا کر کہ تیرے بندے اسے پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھاویں اور تیرے
برگزیدہ رسول کے پاک نمونہ پر چل کر تیری رضا حاصل کریں اور اے میرے مولا !
تو مجھے بھی توفیق عطا کر کہ میں تیری رضا کے ماتحت اس کتاب کے باقی حصوں کی
تکمیل کرسکوں اور اپنے فضل کو میرے شامل حال رکھ.وَاخِرُ دَعُونَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - أَمِينِ
را قم آغم
مرزا بشیر احمد
Page 300
صلی اللہ علیہ وسلم
سیرت خاتم النبیین
Page 302
۲۸۷
بسم الله الرّحمن الرّحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
عرض حال
جلد دوم
سيرة خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل دیباچہ تو تکمیل تصنیف کے وقت ہی لکھا جا سکے گا مگر اس جگہ
چند الفاظ حصہ دوم کے متعلق مخصوص طور پر عرض کرنے ضروری ہیں.ابتداء ۱۹۱۹ء میں جب میں نے
بطور خود رساله ریویوآف ریلیجنز قادیان کے لئے سیرة کی تصنیف کا کام شروع کیا تو اس وقت اس کی
غرض و غایت بہت محدود تھی.چنانچہ سیرۃ کا حصہ اوّل جو ۱۹۲۰ء میں کتابی صورت میں شائع ہوا وہ اسی
محدودغرض و غایت کے ماتحت تھا جو صرف یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمان نوجوانوں کے لئے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سادہ اور مختصر سوانح عمری میسر آ جاوے.کوئی علمی تحقیق یا محققانہ تبصرے اس وقت
میرے مدنظر نہ تھے.چنانچہ اسی غرض سے حصہ اول میں حوالے تک درج نہیں کئے گئے.اس کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت خلیفتہ امسیح الثانی امام جماعت احمد یہ قادیان کو اس کام کی تکمیل کی
طرف توجہ پیدا ہوئی اور آپ نے ۱۹۲۹ء کے اوائل میں مجھے سیرت کے حصہ دوم کی تیاری کے متعلق ارشاد
فرمایا تو ساتھ ہی یہ ہدایت فرمائی کہ ہر قسم کے طبقہ کو مدنظر رکھ کر اس حصہ میں حصہ اوّل کی نسبت زیادہ مستقل
تحقیق و تدقیق سے کام لیا جاوے لیکن یہ کوشش کی جاوے کہ کتاب کا حجم حتی الوسع زیادہ نہ ہونے پائے.جس حد تک میں اس ہدایت کی تعمیل کر سکا ہوں وہ اب حصہ دوم کی
صورت میں ناظرین کے سامنے ہے.اگر اس کے بعض حصوں میں میں نے حد مناسب سے زیادہ طوالت
سے کام لیا ہے تو وہ غالبا میرے اس طبعی نقص کی وجہ سے ہے
کہ میں تحریر میں اختصار پر زیادہ قابونہیں رکھ
سکتا اور میں ڈرتا ہوں کہ شاید اس جہت سے میں حضرت خلیفتہ امسیح ایدہ اللہ بنصرہ کی ہدایت پر پوری طرح
Page 303
۲۸۸
عمل نہیں کر سکا.تحقیق و تدقیق کی جہت سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں.یہ میدان اس قدر وسیع ہے کہ اگر اسے
ایک نہ ختم ہونے والا میدان کہ سکیں تو بے جانہ ہوگا.میرے اپنے احساس کا یہ حال ہے کہ جب بھی میں
نے سیرت کے مسودے کی نظر ثانی کی ہے مجھے اس میں قریباً ہمیشہ ہی تحقیق کے لئے ایک نیا دروازہ نظر آیا
ہے اور بعض حصے تو یقیناً ایسے ہیں کہ ان میں مزید تحقیق کی ضرورت عیاں ہے مگر فی الحال جو کچھ بھی ہے وہ
ہد یہ ناظرین ہے اور خدا سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اسے قبولیت کا شرف عطا کرے اور اس کے
ذریعہ سے اس مقصد کو پورا فرمائے جو اس کی تصنیف کی اصل غرض و غایت ہے.اللھم آمین.حصہ دوم کے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ حصہ اوّل کی نسبت اس حصہ میں چار زائد خصوصیات
ہیں: اول زیادہ تحقیق و تدقیق.دوم زیادہ تفصیل و تشریح.سوم بہت سے
شکمی اور ضمنی مسائل کی بحث.چہارم حوالہ جات کا اندراج.ان خصوصیات کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اگر اور جب حصہ اوّل کا
دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو اسے ان مزید خصوصیات کی روشنی میں نظر ثانی کرنے کے
بعد شائع کیا جاوے ورنہ یہ دونوں حصے بالکل غیر مربوط نظر آئیں گے.جن کتب سے میں نے حصہ دوم کی تیاری میں استفادہ کیا ہے ان کا اندازہ صرف ان اسماء سے نہیں
لگ سکتا جو حوالہ کی صورت میں حاشیہ میں درج ہوئے ہیں.بالعموم متاخرین کی کتب کے حوالے درج نہیں
کئے گئے کیونکہ جب بھی مجھے ان کتب میں کوئی نئی یا مفید بات ملی ہے تو میں نے بجائے ان کتب کا حوالہ
دینے کے ان کے ماخذ کی طرف رجوع کر کے اصل کتاب کا حوالہ درج کر دیا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس وجہ
سے متاخرین کی کتب کی طرف سے میرے جذ بہ تشکر میں کوئی کمی نہیں آ سکتی.ممکن ہے کہ بعض طبائع میں یہ سوال پیدا ہو کہ مولانا شبلی کی سیرت کے ہوتے ہوئے اس تصنیف کی کیا
ضرورت
تھی ؟ اس سوال کا اصل جواب تو ہر دو کتب کے مطالعہ سے ہی مل سکتا ہے لیکن میں اس قد رعرض کرنا
لمصنفین
ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے سیرۃ النبی کی خوبیوں کا اعتراف ہے اور میں نے بعض جگہ اس سے اور دارا
کی دوسری تصنیفات سے فائدہ بھی اٹھایا ہے مگر تحقیق کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور پھر ہر شخص کا نقط نظر
اور اسلوب بیان بھی جدا ہوتا ہے اس لئے میری یہ ناچیز کوشش کسی کے ناگوار خاطر نہیں ہونی چاہئے بلکہ اگر
کل کو کوئی اور شخص اپنی کوئی جدید تحقیق یا کوئی جدید نقط نظر اور جدید اسلوب بیان دنیا کے سامنے پیش کرے
تو یقینا اسلامی لٹریچر کی یہ ایک مزید خوش قسمتی ہوگی.ولكل امرء مانوی و انما الاعمال بالنيات
Page 304
۲۸۹
میرے لئے اس جگہ ان بزرگان و احباب کرام کا شکر یہ ادا کرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے اس کتاب
کی تیاری میں کسی نہ کسی رنگ میں امداد فرمائی ہے.حضرت خلیفہ المسیح الثانی امام جماعت احمد یہ ایدہ اللہ
بنصرہ العزیز نے کمال مہربانی سے اپنا نہایت قیمتی وقت خرچ کر کے حصہ دوم کے مسودے کا بیشتر حصہ ملاحظہ
فرمایا اور وقتاً فوقتاً اپنے بیش قیمت ارشادات سے مستفیض ہونے کا موقع عطا کیا.حضرت مولوی شیر علی
صاحب بی.اے ناظر تالیف و تصنیف جماعت احمدیہ قادیان نے قریباً ساری کا پیاں ملاحظہ کیں اور مجھے
ان کی تصحیح میں امداد دینے کے علاوہ بعض جگہ مفید مشورے بھی دئے.مولوی عبدالرحیم صاحب درد
ایم.اے سابق مبلغ اسلام لنڈن نے مسودے کے بعض خاص خاص حصے دیکھے اور مجھے اپنی قیمتی رائے
سے مستفید کیا.مولوی ارجمند خان صاحب مولوی فاضل پروفیسر جامعہ احمدیہ قادیان نے کاپیوں کی درستی
میں بہت قابل قدرا مداددی.فجزاهم الله خيراً.اسی طرح مینجر بکڈ پوتالیف واشاعت قادیان اور
مینجر اله بخش سٹیم پر لیس قادیان اور کاتب کتاب ہذا بھی اپنی ہمدردانہ توجہ کی وجہ سے قابل شکر ہیں.خاکسار
مرزا بشیر احمد
کارکن نظارت تالیف و تصنیف جماعت احمدیہ قادیان
۳۰ / مارچ ۱۹۳۱ء
Page 306
۲۹۱
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
مدینہ کا ابتدائی قیام اور حکومت اسلامی کی تاسیس
مدینہ کے حالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ہجرت کا بیان کتاب کے حصہ
اول میں گزر چکا ہے.اب ہجرت کے بعد سے آپ کی مدنی زندگی کا آغاز ہوتا
ہے.لیکن پیشتر اس کے کہ ہم آپ کی مدنی زندگی کا بیان شروع کریں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ خود مدینہ
اور اس کی آبادی کا مختصر حال بیان کر دیا جاوے کیونکہ اس کے بغیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی
کے بعض حالات کا پوری طرح سمجھنا مشکل ہے.یہ بتایا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت
سے
قبل مدینہ کا شہر یثرب کے نام سے مشہور تھا لیکن آپ کی ہجرت کے بعد لوگ اسے مدينة الرسول (یعنی
خدا کے رسول کا شہر ) کہہ کر پکارنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا نام صرف مدینہ مشہور ہو گیا.مدینہ عرب
کے علاقہ حجاز کا قدیم شہر ہے جو مکہ سے شمال کی طرف دواڑھائی سو میل کے فاصلہ پر بحر احمر کے مشرقی ساحل
سے قریباً پچاس میل مشرق کی طرف ہٹ کر واقع ہے.گویا مدینہ اس قدیم مگر صحرائی تجارتی راستے کے قرب
میں آباد ہے جو مکہ سے شام کی طرف جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ مکہ اور شام کے درمیان آنے جانے والے
تاجر بعض اوقات راستے سے کچھ ہٹ کر مدینہ میں بھی قیام کرتے جاتے تھے اور اس لئے مکہ اور مدینہ کے
بہت سے لوگ آپس میں روشناس تھے اور بعض تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی رکھتے تھے.جگہ کے لحاظ سے مدینہ کو ایک وادی کہنا چاہئے جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی اور
انہی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی اُحد تھی جہاں بعد میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک
نہایت خطرناک جنگ وقوع میں آئی.عرب کے دوسرے مقامات کے مقابلہ میں مدینہ میں بارش
عموماً خاصی ہو جاتی ہے اور زمین بھی ویسی رتیلی اور ناقص نہیں جوعمو ماعرب کے دوسرے حصوں میں پائی جاتی
Page 307
۲۹۲
ہے.یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے باشندے قدیم زمانہ سے عموماً زراعت پیشہ رہے ہیں.مدینہ میں گرمی
شدت کی پڑتی ہے اور سرما میں سردی بھی بہت تیز ہوتی ہے اور جس زمانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں
مدینہ میں ملیریا وغیرہ کی وبا بھی بہت پڑتی تھی اور لوگ بخار سے سخت تکلیف اٹھاتے تھے.چنانچہ جب
شروع شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو بوجہ
آب و ہوا کی تبدیلی کے انہوں نے بہت تکلیف اُٹھائی اور بہت سے مسلمان بخار میں مبتلا ہو گئے اور
ان کی صحتوں کو بہت نقصان پہنچا.چنانچہ احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا مروی ہے
جو آپ نے مسلمانوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر خدا کے حضور کی اور جس کے نتیجہ میں خدا نے مسلمانوں کو
اس تکلیف سے نجات دی اور مدینہ کی فضا ایک بڑی حد تک وبائی جراثیم سے پاک ہوگئی ہے
اس زمانہ میں مدینہ کی آبادی اکٹھی نہیں تھی بلکہ کسی قدر پھیلی ہوئی تھی اور ہر قوم الگ الگ حصوں میں
آباد تھی اور خود حفاظتی کے لئے سب نے اپنے اپنے واسطے چھوٹے چھوٹے قلعے سے بنارکھے تھے.پرانی
روایات سے پتہ لگتا ہے کہ یثرب میں سب سے پہلے آباد ہونے والے لوگ عمالیق قوم کے آدمی تھے
جنہوں نے وہاں کھجوروں کے باغات لگائے اور چھوٹے چھوٹے قلعے تیار کئے.ان کے بعد یہودی لوگ
آباد ہوئے.ان یہود کے متعلق روایات میں اختلاف ہے کہ وہ نسلاً عرب تھے یا کہ باہر سے آئے
تھے.مگر عام مؤرخین کی رائے یہی ہے کہ وہ زیادہ تر بنی اسرائیل تھے جو اپنے وطن سے نکل کر عرب میں
آکر آباد ہو گئے تھے اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ عرب کے بعض اصلی باشندے بھی ان کا مذہب اختیار
کر کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے.بہر حال عمالیق کے بعد مدینہ میں یہود آ کر آباد ہوئے اور انہوں نے
آہستہ آہستہ عمالیق کو نیست و نابود یا جلاوطن کر کے ان کی جگہ خود لے لی.یہ یہود تین بڑے قبائل میں منقسم
تھے یعنی بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ.یہ تینوں قبائل شروع میں عموماً بہت اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے
تھے.ان یہود نے بھی اس زمانہ کے دستور کے مطابق اپنی رہائش کے لئے چھوٹے چھوٹے قلعے تیار کئے
جو ایک دوسرے سے ملحق نہ تھے بلکہ تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر مدینہ کے آس پاس پھیلے ہوئے تھے.یہود کا
پیشہ عموماً تجارت تھا، ان میں سے بعض زراعت کا شغل بھی رکھتے تھے.بنو قینقاع زیادہ تر صناعی کا کام
کرتے تھے.یہود چونکہ اپنے اردگرد کے لوگوں کی نسبت زیادہ مہذب و متمدن تھے اور تعلیم میں بھی آگے
تھے.اس لئے انہوں نے مدینہ کے گردو نواح میں اپنا اثر پیدا کرنا شروع کیا اور جلد ہی بہت اقتدار حاصل
: بخاری ابواب الہجرت.ابن ہشام جلد اصفحہ ۲۱۵.میں جلد اصفحہ ۳۹۵
Page 308
۲۹۳
کر لیا.وہ اسی اقتدار کی حالت میں تھے کہ یمن کی طرف سے بنو قحطان کے دو قبیلے جو اوس اور خزرج کے
نام سے پکارے جاتے تھے مدینہ میں آکر آباد ہوئے.یہ قبائل ایک شخص حارثہ بن ثعلبہ کے دو بیٹوں اوس
اور خزرج کی اولاد تھے اور آپس میں بہت اتفاق و محبت کے ساتھ رہتے تھے.شروع شروع میں تو وہ یہود
سے بالکل الگ تھلگ رہے لیکن آخر یہود کے زور اقتدار کی وجہ سے اُن کے حلیف بن گئے.اس کے بعد آہستہ آہستہ اوس وخزرج نے بھی پھیلنا اور زور پکڑنا شروع کیا اور کچھ کچھ یہود کی ہمسری
کا دم بھر نے لگے لیکن چونکہ یہودی لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ متمدن اور زیادہ با اثر ہونے کے علاوہ تعلیم
اور اُمور مذہبی میں بھی زیادہ دخل رکھتے تھے اور اوس و خزرج محض بت پرست اور عموماً جاہل تھے اس لئے
اوس وخز رج پر یہود کا ایک گہرا اثر تھا حتی کہ جب کبھی کسی اوسی یا خزرجی شخص کے کوئی نرینہ اولاد نہ ہوتی تو
وہ یہ منت مانتا تھا کہ اگر میرے گھر لڑکا پیدا ہوا تو میں اُسے یہودی بناؤں گا.چنانچہ اسی طرح کئی لوگ یہودی
بن گئے اور ان کا زوردن بدن بڑھتا گیا.حتیٰ کہ یہودیوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اوس وخزرج پر
طرح طرح کے مظالم شروع کر دئے جس کے نتیجہ میں یہود اور اوس وخزرج کے تعلقات بہت خراب
ہو گئے اور بالآخر مؤخر الذکر قبائل نے تنگ آکر ریاست غسان کے فرمانروا کی امداد سے یہود کے تمام
سر بر آوردہ لوگوں کو ہوشیاری سے قتل کروا دیا.جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کا زور ٹوٹ گیا اور
اوس وخزرج شہر میں طاقت پکڑ گئے لیکن یہود کے کمزور ہو جانے کا آہستہ آہستہ یہ اثر بھی ظاہر ہونے لگا کہ
اوس و خزرج جو اس وقت تک یہود کے مقابلہ کی وجہ سے آپس میں اتحاد واتفاق کے ساتھ رہتے تھے اب
آپس میں لڑنے اور جھگڑنے لگ گئے اور بالآخر یہ خانہ جنگیاں ایسی وسیع اور خطر ناک صورت پکڑ گئیں کہ
دونوں تو میں آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے کٹ کٹ کر بہت کمزور ہوگئیں اور یہود کو جو غالباً
اس خانہ جنگی کی آگ کو بھڑ کانے والے تھے پھر طاقت پکڑ جانے کا موقع مل گیا.نتیجہ یہ ہوا کہ اوس وخزرج
نے پھر یہودی قبائل کی امداد کا سہارا ڈھونڈا اور ایک دوسرے کے خلاف ان کی مدد چاہی.چنانچہ
بنو قینقاع قبیلہ خزرج کے حلیف بن گئے اور بنو نضیر اور بنوقریظہ قبیلہ اوس کے ، اور اس طرح سارا شہر ایک
خطر ناک خانہ جنگی کی آگ سے شعلہ بار ہوگیا.اہل میثرب اسی خانہ جنگی کی حالت میں تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے حکم پا کر مکہ میں
نبوت کا دعویٰ کیا.چنانچہ اوس و خزرج کے درمیان آخری جنگ جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام
سے مشہور ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں ہی ہوئی تھی جب کہ آپ مکہ میں مقیم
Page 309
۲۹۴
تھے.اس لڑائی میں اس قدر خونریزی ہوئی اور فریقین کے اتنے آدمی مارے گئے کہ اوس اور خزرج
نا چار آپس میں صلح کرنے پر مجبور ہو گئے.چنانچہ دونوں قبیلوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس بات پر
اتفاق کرلیا کہ چند شرائط کے ماتحت عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو قبیلہ خزرج کا ایک نامور اور ہوشیار رئیس
تھا اپنا متحدہ سردار تسلیم کر لیا جاوے اور عبداللہ کی باقاعدہ تاجپوشی کی تیاری ہونے لگی مگر عبداللہ کا سر
ہنوز قبائل اوس وخزرج کی سرداری کے تاج سے مزین نہ ہونے پایا تھا کہ اسلام کی آواز مدینہ تک پہنچ
گئی اور حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا.یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے مدینہ تشریف لانے کو ایک ایسے رقیب کی آمد سمجھا جس نے اس سے اوس اور خزرج کی سرداری کا مجوزہ
تاج چھین لیا.چنانچہ اس کے دل میں حسد و عداوت کی آگ سلگنے لگ گئی اور چونکہ وہ اتنی جرات نہیں
رکھتا تھا کہ اپنے قبیلہ والوں کے خلاف ہو کر کھلم کھلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کھڑا ہو سکے
اس لئے اُس نے بر ملاطور پر مخالفت کرنے کی بجائے خفیہ عداوت اور ریشہ دوانی کا طریق شروع کر دیا اور
جنگ بدر کے بعد اس نے بظاہر اسلام بھی قبول کر لیا، مگر اس کے دل کا یہ مرض کم نہ ہوا اور آخر اسی حالت
میں اس نے جان دی لے
نزول قبا.۲۰ ستمبر ۶۲۲ء مدینہ اور اس کی آبادی کے یہ مختصر حالات بیان کرنے کے بعد ہم اپنے
اصل مضمون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ جب
انصار کے کانوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آواز پہنچی تو مدینہ کا میدان تکبیر کے نعروں سے
گونج اٹھا اور لوگ جلدی جلدی اپنے ہتھیاروں کو درست کر کے نہایت شوق کے ساتھ اس سمت میں لپکے
جدھر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے.یہ وقت بھی ایک عجیب وقت تھا.سرور عالم یعنی
خدا کا وہ مقدس فرستادہ جس کے وجود میں نبوت ورسالت کے پیغام نے اپنے کمال کو پہنچنا تھا اپنے
عزیز واقارب کے مظالم سے تنگ آکر اپنے وطن سے نکلتا ہے اور ایک ایسی بستی کی طرف آتا ہے جو د نیوی
رشتہ کے لحاظ سے گویا ایک غیروں کی بستی ہے مگر خدا انہی غیروں کے دلوں میں وہ محبت ڈال دیتا ہے کہ جس
کے سامنے خون کے رشتے کی محبت بالکل بیچ نظر آتی ہے اور آج سے مدینہ کے اوس وخزرج کی قسمت
اسلام کے نوشتہ تقدیر کے ساتھ اس طرح مخلوط طور پر بن دی جاتی ہے کہ ناممکن ہے کہ دنیا کا کوئی مورخ
ایک کے ذکر سے دوسرے کے ذکر کو جدا کر سکے.بیشک اسلام نے عرب کے ان بادیہ نشینوں کو جن کے
-
1 : مدینہ اور اس کی آبادی کے حالات کتاب معجم البلدان اور الروض الانف اور دیگر کتب تاریخ و جغرافیہ سے ماخوذ ہیں.
Page 310
۲۹۵
بیشتر اوقات شراب اور زنا اور جوئے اور آپس کی لڑائی میں گزرتے تھے ایک تاریک ترین قعر مذلت سے
اٹھایا اور ایک روشن ترین اوج سعادت پر پہنچا دیا اور اسلام پر کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ ہر اک مسلمان کی
گردن اسلام کے احسان کے نیچے ہے، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان ابتدائی فدایان اسلام
نے جس جاں نثارانہ قربانی اور جس والہانہ عشق و محبت سے اسلام کے نازک اور کم سن پودے کو اپنے خون
کے پانی سے سینچا اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی.مگر مجھے اپنے مضمون کی طرف لوٹنا چاہئے.انصار کی
نظریں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو ان کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے اور انہوں نے ایسا
محسوس کیا کہ گویا دنیا و آخرت کے سارے انعامات انہیں آپ کے وجود میں حاصل ہو گئے ہیں.چنانچہ
بخاری میں براء بن عازب کی روایت ہے کہ جو خوشی انصار کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف
لانے کے وقت پہنچی ویسی خوشی کی حالت میں میں نے انہیں کبھی کسی اور موقع پر نہیں دیکھا.ترمذی اور
ابن ماجہ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے
یوں محسوس کیا کہ ہمارے لئے مدینہ روشن ہو گیا اور جب آپ فوت ہوئے تو اس دن سے زیادہ تاریک
ہمیں مدینہ کا شہر کبھی نظر نہیں آیا.استقبال کرنے والوں کی ملاقات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیال کے ماتحت جس کا ذکر
تاریخ میں نہیں آیا سید ھے شہر کے اندر داخل نہیں ہوئے بلکہ دائیں طرف ہٹ کر مدینہ کی بالائی آبادی میں
جو اصل شہر سے دو اڑھائی میل کے فاصلہ پر تھی اور جس کا نام قبا تھا تشریف لے گئے.اس جگہ انصار کے
بعض خاندان آباد تھے جن میں زیادہ ممتاز عمر و بن عوف کا خاندان تھا اور اس زمانہ میں اس خاندان کے
رئیس کلثوم بن الہدم تھے.قبا کے انصار نے آپ کا نہایت پر تپاک استقبال کیا اور آپ کلثوم بن الہدم
کے مکان پر فروکش ہو گئے.وہ مہاجرین جو آپ سے پہلے مدینہ پہنچ گئے ہوئے تھے وہ بھی اس وقت تک
زیادہ تر قبا میں کلثوم بن الہدم اور دوسرے معززین انصار کے پاس مقیم تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ
آپ نے سب سے پہلے قبا میں قیام کرنا پسند فرمایا.ایک آن کی آن میں سارے مدینہ میں آپ کی آمد کی
خبر پھیل گئی اور تمام مسلمان جوش مسرت میں بیتاب ہو کر جوق در جوق آپ کی فرودگاہ پر جمع ہونے شروع
ہو گئے.اس وقت ایک عجیب لطیفہ ہوا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی سادگی کا پتہ چلتا ہے
اور وہ یہ کہ جن اہالیان مدینہ نے آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا ان میں سے بعض اپنے خیال میں
ل : زرقانی جلد اصفحه ۳۵۹
Page 311
۲۹۶
حضرت ابوبکر کو ہی رسول اللہ سمجھتے رہے مگر جب مجلس میں دھوپ آگئی اور حضرت ابو بکر نے اپنی چادر سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا اس وقت ان کی یہ غلط فہمی دور ہوئی.اس غلط فہمی کی وجہ یہ تھی کہ
باوجو د عمر میں چھوٹا ہونے کے حضرت
ابو بکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زیادہ بوڑھے نظر آتے تھے
اور بمقابلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بہت سے بال سفید ہو چکے تھے اور چونکہ مجلس میں نشست
کی کوئی خاص ترتیب بھی نہیں تھی اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی ممتاز جگہ معین تھی اس لئے
نا واقف لوگوں کو دھوکا لگ گیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول قبایعنی تکمیل سفر ہجرت کی تاریخ کے متعلق روایات میں کسی قدر
اختلاف ہے.عام مؤرخین کا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن اور ربیع الاول ۱۴ نبوی کی بارہ تاریخ تھی مگر بعض
محققین نے آٹھ تاریخ لکھی ہے.عیسوی سن کے شمار سے یہ تاریخ بعض حساب دانوں کے خیال کے
مطابق ۲۰ ستمبر ۶۲۲ تھی.اسلامی سن کا شمار اسی واقعہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے مگر سال کی ابتدار بیع الاول
سے نہیں ہوتی جو کہ ہجرت کا مہینہ ہے بلکہ محرم سے ہوتی ہے جو کہ قمری مہینوں کا پہلا ماہ سمجھا جاتا ہے اور
اس طرح پہلا سال ہجرت کا دراصل بارہ ماہ کا نہیں تھا بلکہ نو ماہ اور کچھ دن کا تھا.اس بارہ میں مؤرخین میں
اختلاف ہے کہ اسلام میں ہجرت کے سن کا حساب ابتداء کس کے عہد میں شروع ہوا.حاکم نے اکلیل میں
روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کے بعد اس کا حکم دیا تھا.لیکن دوسری روایات
کی بنا پر جمہور مورخین کا یہ خیال ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ حساب حضرت عمرؓ کے عہد خلافت
میں شروع ہوا تھا.واللہ اعلم
مؤرخین لکھتے ہیں کہ پہلا کام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیا د رکھی اور صحابہ نے مل کر مزدوروں
اور معماروں کا کام کیا.اور چند دن کی محنت سے یہ مسجد تیار ہوگئی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد
سے آخر وقت تک بہت محبت رہی.چنانچہ مدینہ میں چلے جانے کے بعد آپ ہر ہفتہ قبا تشریف لے
جاتے اور اس مسجد میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے.بعض علماء کا خیال ہے کہ قرآن شریف میں جس مسجد کے
متعلق أُسِسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ یہی مسجد قبا ہے اور اس میں
2 : بخاری باب الحجرت
: زرقانی
توفیقات الہامیه محمد مختار پاشا مصری
: طبری
۵: توبه : ۱۰۸
Page 312
۲۹۷
شک نہیں ہے کہ گو اس سے پہلے بھی بعض مسجد میں مسلمانوں نے بنائی تھیں لیکن یقیناً قبا کی مسجد اسلام میں
وہ پہلی مسجد تھی جس کی بناء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تکمیل ہجرت کے بعد پہلے دن رکھی گئی
اور جسے مسلمانوں نے گویا ایک قومی عبادت گاہ کے طور پر تعمیر کیا.یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے اپنی جگہ حضرت علیؓ کو
چھوڑ آئے تھے اور ان کو تاکید فرما آئے تھے کہ امانتیں وغیرہ واپس کر کے بہت جلد مدینہ پہنچ جائیں.چنانچہ
ابھی آپ کو قبا میں تشریف لائے صرف تین دن ہی ہوئے تھے کہ حضرت علی بھی مع الخیر قبا میں پہنچ گئے
لیکن ابھی تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مکہ میں ہی تھے.ورود مدینہ اور جمعہ کی پہلی نماز غالبا ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں ہی مقیم تھے کہ
مسلمانان مدینہ میں اس بات کے متعلق گفتگو شروع ہوئی کہ
مدینہ میں آپ کس کے ہاں قیام فرما ہوں گے.ہر ایک خاندان یہ چاہتا تھا کہ اسے آپ کی میزبانی کا
فخر حاصل ہو.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اختلاف پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں عبدالمطلب کے
ننھیال بونجار کے ہاں ٹھہروں گا.یہ ایک نہایت حکیمانہ فیصلہ تھا جس سے آپ نے انصار کے مختلف
قبائل میں نا واجب جذبات رقابت کے پیدا ہونے کا سد باب فرما دیا اور آپ کے اس ارشاد پر سب کی
تسلی ہوگئی کیونکہ گوایمان وا خلاص میں سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے لیکن بنوسنجار کو یہ ایک مزید
اور مسلّم خصوصیت حاصل تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کی والدہ سلمی اسی خاندان
سے تعلق رکھتی تھیں.قبا میں زائد از دس دن کے قیام کے بعد جمعہ کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندرونی
حصہ کی طرف روانہ ہوئے.انصار و مہاجرین کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی.آپ ایک اونٹنی پر
سوار تھے اور حضرت ابوبکر آپ کے پیچھے تھے.یہ قافلہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھنا شروع ہوا.راستہ
میں ہی نماز جمعہ کا وقت آگیا.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کے محلہ میں ٹھہر کر صحابہ
کے سامنے خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز ادا کی.مؤرخین لکھتے ہیں کہ گو اس سے پہلے جمعہ کا آغاز ہو چکا تھا.کے
مگر یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے خود ادا کیا.اور اس کے بعد سے جمعہ کی نماز کا طریق با قاعدہ جاری ہو گیا.2 : مسلم باب الحجرت
: ابوداؤ دباب الجمعہ فی القریٰ
سے : بخاری باب البجرت عن عائشہ
: ابن ہشام ذکر ہجرت
Page 313
۲۹۸
دراصل جمعہ نمازوں کی عید ہے جیسا کہ روزوں کی عید عید الفطر اور حج کی عید عید الاضحیٰ ہے اور اسی لئے
شریعت اسلامی میں جمعہ کی نماز کو بہت اہمیت دی گئی ہے.اس نماز میں امام ایک خطبہ دیتا ہے جس میں
حاضر الوقت مسائل پر تقریر ہوتی ہے اور حاضرین کو ایمان و اعمال کے متعلق مناسب نصائح کی جاتی ہیں
اور اس کے بعد دورکعت نماز فرض ادا کی جاتی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم ہے کہ حتی الوسع
ہر مسلمان کو چاہئے کہ جمعہ کے دن غسل کرے اور کپڑے بدلے اور خوشبو لگائے اور خطبہ شروع ہونے
سے
قبل مسجد میں پہنچ جاوے.جس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جمعہ ادا کیا.اس جگہ اب ایک
مسجد ہے جسے اس جمعہ کی یادگار میں مسجد الجمعہ کہتے ہیں.جمعہ سے فارغ ہو کر آپ کا قافلہ پھر آہستہ آہستہ آگے روانہ ہوا.راستہ میں آپ مسلمانوں کے
گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ جوش محبت میں بڑھ بڑھ کر عرض کرتے تھے 'یا رسول اللہ ! یہ ہمارا
گھر یہ ہمارا مال و جان حاضر ہے اور ہمارے پاس حفاظت کا سامان بھی ہے آپ ہمارے پاس تشریف فرما
ہوں.آپ ان کے لئے دعائے خیر فرماتے اور آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھتے جاتے تھے.مسلمان
عورتوں اور لڑکیوں نے خوشی کے جوش میں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر گانا شروع کیا.طَلَعَ البَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَى لِلَّهِ دَاع
یعنی آج ہم پر کوہ وداع ع کی گھاٹیوں سے چودھویں کے چاند نے طلوع کیا ہے.اس لئے اب ہم پر
ہمیشہ کے لئے خدا کا شکر واجب ہو گیا ہے.مسلمانوں کے بچے مدینہ کی گلی کوچوں میں گاتے پھرتے تھے
کہ محمدصلی اللہ علیہ وسلم آگئے.خدا کے رسول آگئے.اور مدینہ کے حبشی غلام آپ کی تشریف آوری کی
خوشی میں تلوار کے کرتب دکھاتے پھرتے تھے.جب آپ شہر کے اندر داخل ہوئے تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی
کہ آپ اس کے پاس قیام فرما ئیں اور ہر شخص بڑھ بڑھ کر اپنی خدمت پیش کرتا تھا.آپ سب کے ساتھ
محبت کا کلام فرماتے اور آگے بڑھتے جاتے تھے.حتی کہ آپ کی ناقہ بنو نجار کے محلہ میں پہنچی اس جگہ بنو نجار
کے لوگ ہتھیاروں سے سجے ہوئے صف بند ہو کر آپ کے استقبال کے لئے کھڑے تھے اور قبیلہ کی لڑکیاں
ل : زرقانی جلد اصفحه ۳۵۹ مطبوعہ مصر بمطبع الازہر بیت المصرية ۱۳۲۵ھ
: وداع ایک پہاڑی یا بعض روایتوں کی رو سے وہ مختلف الحبت پہاڑیوں کا نام ہے جہاں مدینہ والے اپنے مسافروں کو
رخصت کیا کرتے تھے اور باہر سے آنے والوں کا استقبال بھی یہیں کیا جاتا تھا.
Page 314
۲۹۹
دفیں بجا بجا کر یہ شعر گارہی تھیں.نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي نَجَّارِ يَا حَبَّذَا مُحَمَّداً مِنْ جَارٍ
یعنی ہم قبیلہ بنو نجار کی لڑکیاں ہیں اور ہم کیا ہی خوش قسمت ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے محلہ میں ٹھہرنے کے لئے تشریف لائے ہیں.بنو نجار میں پہنچ کر پھر یہ سوال در پیش تھا کہ آپ کس
شخص کے ہاں مہمان ٹھہریں.قبیلہ کا ہر شخص خواہشمند تھا کہ اسی کو یہ فخر حاصل ہو بلکہ بعض لوگ تو جوش محبت
میں آپ کی اونٹنی کی باگوں پر ہاتھ ڈال دیتے تھے.اس حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا.” میری اونٹنی
کو چھوڑ دو کہ یہ اس وقت مامور ہے.یعنی جہاں خدا کا منشا ہوگا وہاں یہ خود بیٹھ جائے گیا ور یہ کہتے
ہوئے آپ نے بھی اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں.اونٹنی آگے بڑھی اور تھوڑی دور خراماں خراماں چلتی ہوئی
جب اس جگہ میں پہنچی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تعمیر ہوئے اور جو
اس وقت مدینہ کے دو بچوں کی افتادہ زمین تھی تو بیٹھ گئی لیکن فوراً ہی پھر اٹھی اور آگے کی طرف چلنے لگی.مگر چند قدم چل کر پھر لوٹ آئی اور اسی جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرما یا هذَا إِنْ شَاءَ اللهُ المَنْزِلُ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی منشاء میں یہی ہماری مقام گاہ ہے.اور پھر خدا سے دعا مانگتے ہوئے اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور دریافت فرمایا کہ اپنے آدمیوں میں سے یہاں
سے قریب ترین گھر کس کا ہے ابوایوب انصاری فورا لپک کر آگے ہو گئے اور عرض کیا.یا رسول اللہ ! میرا
،،
ہے اور یہ میرا دروازہ ہے.تشریف لے چلئے.آپ نے فرمایا.”اچھا جاؤ اور ہمارے لئے کوئی
ٹھہرنے کی جگہ تیار کرو.“
ابوایوب انصاری فوراً اپنے مکان کو ٹھیک ٹھاک کر کے آگئے اور آنحضرت صلی اللہ
قیام دارابی ایوب
علیہ وسلم ان کے ساتھ اندر تشریف لے گئے.یہ مکان دومنزلہ تھا.ابوایوب
چاہتے تھے کہ آپ اوپر کی منزل میں قیام فرما ئیں لیکن آپ نے اس خیال سے کہ ملاقات کے لئے آنے
والے لوگوں کو آسانی رہے نچلی منزل کو پسند فرمایا اور وہاں فروکش ہو گئے.رات ہوئی تو ابو ایوب اور ان کی
بیوی کوساری رات اس خیال سے نیند نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم آپ کے اوپر
: بخاری کتاب الحجرت.بخاری میں اونٹنی کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوا مگر یہ ذکر موجود ہے کہ مسجد والی جگہ میں
اونٹنی خود بخود آ کر بیٹھ گئی تھی جس پر آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ یہی ہماری منزل ہے.باقی تفصیل کتب سیر میں ہے.: مسلم جلد ۲ صفحہ ۹۷ اوا بن ہشام
Page 315
ہیں اور مزید ا تفاق یہ ہو گیا کہ رات کو چھت پر ایک پانی کا برتن ٹوٹ گیا اورابوایوب نے اس ڈر سے کہ
پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہ ٹپک جاوے، جلدی سے اپنا لحاف پانی پر گرا کر اسے خشک کر دیا.صبح ہوئی تو وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بکمال اصرار آپ کی خدمت میں اوپر کی منزل
میں تشریف لے چلنے کی درخواست کی.آپ نے پہلے تو تامل کیا لیکن بالآخر ابوایوب کے اصرار کو دیکھ
کر رضا مند ہو گئے.اس مکان میں آپ نے سات ماہ تک یا ابن اسحاق کی روایت کی رو سے ماہ صفر۲ ہجری
تک قیام فرمایا.گویا جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ والے حجرے تیار نہیں ہو گئے آپ اسی جگہ مقیم
رہے.ابوایوب آپ کی خدمت میں کھانا بھجواتے تھے اور پھر جو کھانا بیچ کر آتا تھا وہ خود کھاتے تھے
اور محبت واخلاص کی وجہ سے اُسی جگہ انگلیاں ڈالتے تھے جہاں سے آپ نے کھایا ہوتا تھا.دوسرے
اصحاب بھی عموماً آپ کی خدمت میں کھانا بھیجا کرتے تھے.چنانچہ ان لوگوں میں سعد بن عبادہ رئیس قبیلہ
خزرج کا نام تاریخ میں خاص طور پر مذکور ہوا ہے.انس بن مالک مدینہ کے ایک دس سالہ یتیم بچے
تھے.ان کی والدہ جن کا نام ام سلیم تھا اور جو بہت مخلص تھیں ان کو اپنے ساتھ لے کر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں انس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتی
ہوں آپ اس کے لئے دعا فرماویں اور اپنی خدمت کے لئے اسے قبول فرما دیں.آپ نے ان کے لئے
دعائے خیر کی اور اپنی خدمت میں انہیں منظور فرمایا اور اس کے بعد سے انس بن مالک ہمیشہ آپ کی
خدمت میں رہنے لگ گئے اور آپ کی وفات تک اس خدمت سے جدا نہیں ہوئے.یہ وہی انس ہیں جن
سے بہت سی احادیث کتب حدیث میں مروی ہوئی ہیں اور جو خاص صحابہ میں شمار کئے جاتے ہیں.انس نے
بڑی لمبی عمر پائی اور ۹ ہجری یا ۹۳ ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے جبکہ ان کے سوا غالباً ایک یا دوصحابی اور
زندہ تھے.اپنی آخری عمر میں انس اکثر کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میرے مال
اور میری اولاد میں اتنی برکت ہوئی ہے جو میرے وہم وگمان میں بھی نہیں تھی اور اب مجھے صرف جنت کی
دعا کے پورا ہونے کا انتظار ہے.مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کچھ روپیہ دے کر مکہ
روانہ فرمایا جو چند دن میں آپ کے اور اپنے اہل وعیال کو ساتھ لے کر مع الخیر مدینہ میں پہنچ گئے.ان کے
ساتھ عبداللہ بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے اہل وعیال کو بھی ساتھ لے کر مدینہ پہنچ گئے.ل : مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۹۷ وابن ہشام
Page 316
۳۰۱
تعمیر مسجد نبوی مدینہ کے قیام کا سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا جس جگہ آپ کی انٹی آکر بیٹھی
تھی وہ مدینہ کے دو مسلمان بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی جو حضرت اسعد بن زرارہ
کی نگرانی میں رہتے تھے.یہ ایک افتادہ جگہ تھی جس کے ایک حصہ میں کہیں کہیں کھجوروں کے درخت تھے
اور دوسرے حصہ میں کچھ کھنڈرات وغیرہ تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد اور اپنے حجرات کی
تعمیر کے لئے پسند فرمایا اور دس دینار یعنی قریب نوے روپے میں یہ زمین خرید لی گئی اور جگہ کو ہموار کر کے
اور درختوں کو کاٹ کر مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوگئی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگتے ہوئے
سنگ بنیا درکھا اور جیسا کہ قبا کی مسجد میں ہوا تھا صحابہ نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا جس میں کبھی کبھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت فرماتے تھے.بعض اوقات اینٹیں اٹھاتے ہوئے صحابہ حضرت
عبد اللہ بن رواحہ انصاری کا یہ شعر پڑھتے تھے.هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرَ هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ
یعنی یہ بوجھ خیبر کے تجارتی مال کا بوجھ نہیں ہے جو جانوروں پر لد کر آیا کرتا ہے بلکہ اے ہمارے
مولی ! یہ بوجھ تقویٰ اور طہارت کا بوجھ ہے جو ہم تیری رضا کے لئے اٹھاتے ہیں.“
اور کبھی کبھی صحابہ کام کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ کا یہ شعر پڑھتے تھے
اللَّهُمَّ إِنَّ الْحُجُرَ أَجُرُ الْآخِرَةِ فَارُحَمِ الْأَنْصَارَوَ الْمُهَاجِرَةِ
یعنی اے ہمارے اللہ ! اصل اجر تو صرف آخرت کا اجر ہے.پس تو اپنے فضل سے انصار ومہاجرین
پر اپنی رحمت نازل فرما.جب صحابہ یہ اشعار پڑھتے تھے تو بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آواز کے ساتھ
آواز ملا دیتے تھے اور اس طرح ایک لمبے عرصہ کی محنت کے بعد یہ مسجد مکمل ہوئی یا مسجد کی عمارت پتھروں
کی سلوں اور اینٹوں کی تھی جو کٹڑی کے کھمبوں کے درمیان چن دی گئی تھیں اور چھت پر کھجور کے تنے اور
شاخیں ڈالی گئی تھیں.مسجد کے اندر چھت کے سہارے کے لئے کھجور کے ستون تھے اور جب تک منبر کی تجویز
نہیں ہوئی انہی ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے وقت ٹیک لگا کر
کھڑے ہو جاتے تھے.مسجد کا فرش کچا تھا اور چونکہ زیادہ بارش کے وقت چھت ٹپکنے لگ جاتی تھی اس لئے
ایسے اوقات میں فرش پر کیچڑ ہو جا تا تھا.چنانچہ اس تکلیف کو دیکھ کر بعد میں کنکریوں کا فرش بنوا دیا گیا.ل : بخاری ابواب الہجرت وزرقانی
Page 317
شروع شروع میں مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھا لیکن تحویل قبلہ کے وقت یہ رخ بدل دیا
گیا.مسجد کی بلندی اس وقت دس فٹ اور طول ایک سو پانچ فٹ اور عرض نوے فٹ کے قریب تھا لیکن
بعد میں اس میں توسیع کر دی گئی.مسجد کے ایک گوشے میں ایک چھت دار چبوترہ بنایا گیا تھا جسے صفہ کہتے تھے.یہ ان غریب مہاجرین
کے لئے تھا جو بے گھر بار تھے.یہ لوگ یہیں رہتے تھے اور اصحاب الصفہ کہلاتے تھے.ان کا کام گویا دن
رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا، عبادت کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا تھا.ان
لوگوں کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خبر گیری فرماتے تھے اور جب
کبھی آپ کے پاس کوئی حد یہ وغیرہ آتا تھا یا گھر میں کچھ ہوتا تھا تو اُن کا حصہ ضرور نکالتے تھے.بلکہ بعض
اوقات خود فاقہ کرتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ اصحاب الصفہ کو بھجوا دیتے تھے.انصار بھی ان کی مہمانی
میں حتی المقدور مصروف رہتے تھے اور ان کے لئے کھجوروں کے خوشے لا لا کر مسجد میں لٹکا دیا کرتے تھے یے
لیکن بائیں ہمہ ان کی حالت تنگ رہتی تھی اور بسا اوقات فاقہ تک نوبت پہنچ جاتی تھی اور یہ حالت کئی سال
تک جاری رہی حتی کہ کچھ تو مدینہ کی آبادی کی وسعت کے نتیجہ میں ان لوگوں کے لئے کام نکل آیا اور کچھ
قومی بیت المال سے امداد کی صورت پیدا ہوگئی.مسجد کے ساتھ ملحق طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رہائشی مکان تیار کیا گیا تھا.مکان کیا
تھا ایک دس پندرہ فٹ کا چھوٹا سا حجرہ تھا اور اس حجرہ اور مسجد کے درمیان ایک دروازہ رکھا گیا تھا جس
میں سے گزر کر آپ نماز وغیرہ کے لئے مسجد میں تشریف لاتے تھے.جب آپ نے اور شادیاں کیں تو اسی
حجرہ کے ساتھ ساتھ دوسرے حجرات تیار ہوتے گئے.مسجد کے آس پاس بعض اور صحابہ کے مکانات بھی
تیار ہو گئے.یہ تھی مسجد نبوی جو مدینہ میں تیار ہوئی اور اس زمانہ میں چونکہ اور کوئی پبلک عمارت ایسی نہ تھی
جہاں قومی کام سرانجام دئے جاتے اس لئے ایوان حکومت کا کام بھی یہی مسجد دیتی تھی.یہیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی.یہیں تمام قسم کے مشورے ہوتے تھے.یہیں مقدمات کا فیصلہ کیا
جاتا.یہیں سے احکامات صادر ہوتے تھے.یہی قومی مہمان خانہ تھا اور ضرورت ہوتی تھی تو اسی سے جنگی
قیدیوں کی جبس گاہ کا کام بھی لے لیا جاتا تھا.: ترمذی بحوالہ تلخیص جلدا
Page 318
٣٠٣
سرولیم میور اس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں.گویہ مسجد سامان تعمیر کے لحاظ سے نہایت سادہ اور معمولی تھی لیکن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )
کی یہ مسجد اسلامی تاریخ میں ایک خاص شان رکھتی ہے.رسول خدا اور ان کے اصحاب اسی مسجد
میں اپنے وقت کا بیشتر حصہ گزارتے تھے.یہیں اسلامی نماز کا با قاعدہ باجماعت صورت میں
آغاز ہوا.یہیں تمام مسلمان جمعہ کے دن خدا کی تازہ وحی کو سننے کے لئے مؤدبانہ اور مرعوب
حالت میں جمع ہوتے تھے.یہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اپنی فتوحات کی تجاویز پختہ کیا کرتے
تھے.یہی وہ ایوان تھا جہاں مفتوح اور تائب قبائل کے وفود ان کے سامنے پیش ہوتے
تھے.یہی وہ دربار تھا جہاں سے وہ شاہی احکام جاری کئے جاتے تھے جو عرب کے دور دراز
کونوں تک باغیوں کو خوف سے لرزا دیتے تھے اور بالآخر اسی مسجد کے پاس اپنی بیوی عائشہ
کے حجرے میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی جان دی اور اسی جگہ اپنے دو خلیفوں کے
پہلو بہ پہلو وہ مدفون ہیں.14
یہ مسجد اور اس کے ساتھ کے حجرے کم و بیش سات ماہ کے عرصہ میں تیار ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے نئے مکان میں اپنی بیوی حضرت سودہ کے ساتھ تشریف لے گئے.بعض دوسرے مہاجرین نے بھی
انصار سے زمین حاصل کر کے مسجد کے آس پاس مکانات تیار کر لئے اور جنہیں مسجد کے قریب زمین نہیں مل سکی
انہوں نے دور دور مکان بنالئے اور بعض کو انصار کی طرف سے بنے بنائے مکان مل گئے تھے.ابھی تک نماز کے لئے اعلان یا اذان وغیرہ کا انتظام نہیں تھا.صحابہ عموماً وقت
ابتدائے اذان
کا اندازہ کر کے خود نماز کے لئے جمع ہو جاتے تھے لیکن یہ صورت کوئی قابل اطمینان
نہیں تھی.اب مسجد نبوی کے تیار ہو جانے پر یہ سوال زیادہ محسوس طور پر پیدا ہوا کہ کس طرح مسلمانوں
کو وقت پر جمع کیا جاوے.کسی صحابی نے نصاری کی طرح ناقوس کی رائے دی.کسی نے یہود کی مثال میں
بوق کی تجویز پیش کی.کسی نے کچھ کہا مگر حضرت عمرؓ نے مشورہ دیا کہ کسی آدمی کو مقرر کر دیا جاوے کہ وہ نماز
کے وقت یہ اعلان کر دیا کرے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند
فرمایا اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اس فرض کو ادا کیا کریں ہے چنانچہ اس کے بعد جب نماز کا وقت آتا تھا
بلال بلند آواز سے الصلوةُ جَامِعَةٌ کہ کر پکارا کرتے تھے اور لوگ جمع ہو جاتے تھے بلکہ اگر نماز کے
لے : لائف آف محمد مصنفہ سرولیم میور
: بخاری کتاب الاذان
Page 319
۳۰۴
علاوہ بھی کسی غرض کے لئے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنا مقصود ہوتا تھا تو یہی ندا دی جاتی تھی.اس کے کچھ
عرصہ کے بعد ایک صحابی عبداللہ بن زید انصاری کو خواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور
انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے اس خواب کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ
میں نے خواب میں ایک شخص کو اذان کے طریق پر یہ یہ الفاظ پکارتے سنا ہے.آپ نے فرمایا یہ خواب خدا
کی طرف سے ہے اور عبد اللہ کو حکم دیا کہ بلال کو یہ الفاظ سکھا دیں.عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب بلال نے
ان الفاظ میں پہلی دفعہ اذان دی تو حضرت عمرؓ اسے سن کر جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! آج جن الفاظ میں بلال نے اذان دی ہے بعینہ یہی الفاظ میں نے بھی
خواب میں دیکھے ہیں.اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے
الفاظ سنے تو فرمایا کہ اسی کے مطابق وحی بھی ہو چکی ہے.الغرض اس طرح موجودہ اذان کا طریق جاری
ہو گیا اور جوطریق اس طرح جاری ہوا وہ ایسا مبارک اور دلکش ہے کہ کوئی دوسرا طریق اس کا مقابلہ
نہیں کرسکتا.گویا ہر روز پانچ وقت اسلامی دنیا کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں ہر مسجد سے خدا کی تو حید اور
محمد رسول اللہ کی رسالت کی آواز بلند ہوتی ہے اور اسلامی تعلیمات کا خلاصہ نہایت خوبصورت اور جامع
الفاظ میں لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے.یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ نماز جو اسلامی عبادات میں سب سے افضل
رکعات نماز میں ایزادی
عبادت سمجھی گئی ہے مکہ میں ہی فرض ہو چکی تھی لیکن اب تک سوائے نماز
مغرب کے جس میں تین رکعات تھیں باقی تمام فرض نمازوں میں صرف دو دو رکعات تھیں لیکن ہجرت کے
کچھ عرصہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے حکم پاکر سفر کے لئے تو وہی دو دورکعات نماز رہنے دی
لیکن حضر کے لئے سوائے نماز فجر اور مغرب کے جو اپنی پہلی صورت میں قائم رہیں باقی نمازوں میں چار
چار رکعات فرض کر دیں اور اس طرح سفر و حضر کا امتیاز قائم ہو گیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی
تعلیم میں یہ ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ اس کے تمام احکام میں میانہ روی کو اختیار کیا گیا ہے اور ان عملی
مشکلات کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے جو انسان کو اس کی زندگی میں پیش آتی رہتی ہیں.چنانچہ نماز کے
مسائل میں ہی بہت سے احکام ایسے پائے جاتے ہیں جو حالات کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں مثلاً
ل : ابوداؤ د ترندی وابن ماجہ تفصیلاً اور مؤطا امام مالک اجمالاً
: زرقانی بروایت ابوداؤد وعبدالرزاق جلد اصفحه ۳۷۸
Page 320
۳۰۵
سفر و حضر کی نماز کے امتیاز کے علاوہ جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے نماز کی ظاہری شکل وصورت کا ملحوظ رکھنا عام
حالات میں ضروری ہے لیکن جو شخص بیماری وغیرہ کی وجہ سے نماز کو اس کی مقررہ صورت میں ادا نہ کرسکتا
ہواس کے لئے اجازت ہے کہ ظاہری صورت کو ترک کر کے بیٹھے بیٹھے یا اگر یہ بھی مشکل ہو تو لیٹے لیٹے ہی
نماز ادا کر لے.اسی طرح نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا واجبات میں سے ہے لیکن جب کوئی شخص سفر میں
ہو اور سواری پر بیٹھے ہوئے اسے جہت کا پتہ نہ لگ سکے یا وہ جہت کو قائم نہ رکھ سکے تو اسلام اسے اختیار دیتا
ہے کہ جدھر اس کی سواری کا رخ ہو ادھر منہ کر کے نماز ادا کر لے.اسی طرح نماز کے لئے مقررہ طریق
پر وضو کرنا ضروری ہے لیکن ایسا شخص جسے پانی نہ ملے یا جسے وضو کر نے سے بیماری کا اندیشہ ہو وہ وضو
ترک کرسکتا ہے.وغیر ذالک
اسی طرح دوسرے امور میں بھی جہاں
کہیں کوئی معقول عملی دقت پیدا ہو جاتی ہے اسلام اپنے احکام کی
صورت کو مناسب طور پر بدل کر اس کی جگہ کوئی دوسری صورت پیش کر دیتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اول
تو اسلام کا پیغام ایک عالمگیر وسعت رکھتا ہے جس میں حالات کے اختلاف کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے
اور دوسرے یہ کہ شریعت اسلامی میں اصل مقصود عبادات کی روح ہے اور عبادات کا جسم صرف اس روح
کے بقا اور حفاظت کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور اسی لئے جہاں کہیں بھی حالات کے بدل جانے سے جسم
کا اختیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہاں جسم کو ترک کر کے روح کو اختیار کر لیا جاتا ہے.اس جگہ یہ ذکر بھی بے موقع نہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جملہ عبادات میں سب
سے زیادہ زور نماز پر دیا ہے.آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز مومن کا معراج ہے.نیز فرماتے تھے کہ نماز ایسی
عبادت ہے جس میں بندہ اپنے خدا سے ہمکلام ہوتا اور گویا اس کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے اور آپ کو نماز
سے اس قدر محبت تھی کہ نماز پنجگانہ تو خیر فرض ہی ہے دوسری نوافل نمازیں بھی آپ نہایت کثرت کے
ساتھ پڑھا کرتے تھے اور نماز تہجد یعنی نصف شب کی نماز سے تو آپ کو اتنا شغف تھا کہ آپ نہایت
التزام کے ساتھ بلا ناغہ اس نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے اور روایت آتی ہے کہ آپ اس قدر دیر تک نماز
تہجد میں کھڑے رہتے تھے کہ بعض اوقات آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے اور آپ اکثر فرمایا کرتے
تھے کہ جُعِلَتْ قُرَّةَ عَيْنِي فِی الصَّلوة یعنی نماز تو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور آپ اپنے صحابہ کو نماز
کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو کہ نماز با جماعت میں کیا خوبی ہے تو خواہ انہیں
اپنے گھٹے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آنا پڑے وہ ضرور آئیں.اپنی آخری بیماری میں جبکہ آپ کو غشی پرغشی آتی
Page 321
۳۰۶
تھی اور سخت بے چینی کی حالت تھی آپ نے ایک دفعہ صبح کے وقت اپنے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو
مسجد میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے.یہ نظارہ دیکھ کر آپ کا چہرہ اس قدر خوشی سے تمتما اٹھا جیسے کوئی
مرجھایا ہوا پھول یکلخت شگفتہ ہو جاوے اور بعض روایات میں ہے کہ آخری فقرہ جو آپ کی زبان سے
سنا گیا وہ الصَّلوةُ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ تھا.یعنی میری امت کے لوگو! نماز اور غلاموں کے متعلق میری
تعلیم کو فراموش نہ کرنا.یہودیوں میں پہلا مسلمان اب تک مسلمان ہونے والے لوگوں میں غالباً بعض مسیحی تو شامل
ہو چکے تھے مگر یہودی کوئی نہیں تھا، لیکن اب ہجرت کے بعد یہ سلسلہ
بھی شروع ہوا اور گو یہودیوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی تھوڑے لوگ
ایمان لائے لیکن یہ قوم بھی بالکل محروم نہیں رہی.سب سے پہلا یہودی جو مشرف بہ اسلام ہوا اس کا نام
حصین بن سلام تھا.یہ شخص مدینہ کا رہنے والا تھا اور یہودیوں میں اپنے علم وفضل کی وجہ سے بہت اثر رکھتا
تھا.ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے کہ یہ شخص آپ کے دعوی کوسن کر کچھ کچھ اسلام کی طرف
مائل ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس نے اپنی اس حالت کا کسی سے اظہار نہیں کیا تھا.جب آپ مدینہ میں
تشریف لائے تو یہ شخص خفیہ طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چونکہ طبیعت میں سعادت تھی پہلی
ملاقات میں ہی مسلمان ہو گیا.مسلمان ہونے کے بعد اسے یہ شوق ہوا کہ اس کی قوم کے لوگ بھی اس نور
سے محروم نہ رہیں جس سے خدا نے اس کے سینے کو منور کیا تھا.چنانچہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے درخواست کی کہ آپ یہودیوں کے سر بر آوردہ لوگوں کو اپنے پاس بلائیں اور انہیں اسلام کی تبلیغ کریں
اور ان سے میرے متعلق رائے دریافت فرمائیں کہ میں ان میں کیسا آدمی سمجھا جاتا ہوں تا کہ اگر وہ میرے
متعلق اچھی رائے کا اظہار کریں تو شاید میرے اسلام لانے کی خبر ہی ان کی ہدایت کا موجب ہو جاوے.چنا نچہ حصین بن سلام ایک طرف ہو کر چھپ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عمائد کو اپنے پاس
بلا کر اسلام کی تبلیغ کی مگرانہوں نے نہ مانا.اس کے بعد آپ نے حصین بن سلام کے متعلق رائے دریافت
کی.جس پر انہوں نے حصین کے علم وفضل کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ وہ ہمارا سردار اور ابن سردار ہے
وغیر ذالک.آپ نے کہا دیکھو اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تم بھی مسلمان ہونے کے لئے تیار ہو گے؟
انہوں نے کہا نعوذ باللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ حصین مسلمان ہو جاوے.آپ نے حصین کو آواز دی اور وہ
لے : یہ جملہ حوالہ جات معتبر کتب حدیث سے ماخوذ ہیں
Page 322
۳۰۷
اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر آگئے اور یہودی عمائدہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگو! خدا کا
تقوی اختیار کرو اور اس کے عذاب کو اپنے اوپر مت لو تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمہاری
کتاب میں موجود ہے اور وہ وہی نبی ہیں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا.پس خدا سے ڈرو اور انکار کی طرف
قدم نہ بڑھاؤ.یہ سن کر پہلے تو یہودی لوگ سخت مبہوت ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم حصین کی بات نہیں
مانتے یہ جھوٹا اور کذاب ہے اور پھر حصین بن سلام کو گالیاں دیتے ہوئے آپ کی مجلس سے اٹھ گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے پر حصین کا نام بدل کر عبد اللہ کر دیا اور اسی نام سے وہ
تاریخ وحدیث میں معروف ہیں.دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جب کوئی شخص
مسلمان ہوتا تھا تو عام طور پر اس کا وہی نام رہنے دیتے تھے جو پہلے ہوتا تھا ہاں اگر کسی شخص کا نام مشرکانہ
ہوتا تھا تو آپ اسے بدل دیتے تھے.حصین بن سلام کا نام مشر کا نہ تو نہیں تھا لیکن غالبا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ یہ شخص یہود میں سے پہلا نو مسلم ہے اس کے نام کو خالص اسلامی رنگ
میں بدلنا مناسب خیال فرمایا.اہل فارس میں پہلا مسلمان اسی زمانہ کے قریب قریب سلمان فارسی مسلمان ہوئے.سلمان
ملک فارس کے بسنے والے تھے اور ابتداء زرتشتی مذہب کے پیرو تھے
لیکن فطری سعادت نے اس مذہب کی اس وقت کی حالت پر تسلی نہ پائی اور وہ کسی بہتر مذہب کی تلاش میں
وطن سے نکلے اور بالآخر شام میں آکر عیسائی ہو گئے.اسی زمانہ میں کسی لوٹ مار میں وہ غلام بنالئے
گئے.مگر یہی غلامی ان کے اسلام کا باعث بن گئی.کیونکہ کئی آقاؤں کے تبادلہ کے بعد بالآخر مدینہ کے ایک
شخص نے انہیں خرید کر اپنے پاس رکھ لیا.چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے
تو سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے آہستہ آہستہ روپے کا انتظام کر کے
اپنے آقا سے آزادی حاصل کرلی اور سب سے پہلی مرتبہ وہ غزوہ خندق میں شریک جہاد ہوئے اور انہی
کے مشورے سے خندق کھودی گئی.مسلمان نہایت پارسا اور متقی آدمی تھے اور بالکل درویشانہ زندگی گزارتے
تھے.ان سے ایک دفعہ کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کے باپ کا کیا نام ہے تو انہوں نے نہایت سادگی
سے جواب دیا کہ میں ابن اسلام ہوں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے متعلق فرمایا کہ
سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ یے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں اور ایک دفعہ جب کہ یہ قرآنی آیت
ا : طبقات ابن سعد
Page 323
۳۰۸
نازل ہوئی کہ آئندہ ایک زمانہ میں ایک جماعت صحابہ کی مانند اور انہیں کی تعلیم کی حامل پیدا ہوگی تو صحابہ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ! یہ کون لوگ ہوں گے.اس پر آپ نے
سلمان فارسی پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِندَ القُرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْرَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ
یعنی اگر ایمان ثریا تک بھی اٹھ جائے گا تو ان فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک شخص اسے دنیا میں پھر
قائم کر دے گا.قبیلہ اوس و خزرج کے غیر
مسلم رؤساء یہ ذکر کیا جاچکا ہے کہ مدینہ میں ابھی تک اوس وخزرج
کے بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ بدستور
اپنے مذہب پر قائم تھے.ان میں سے دو شخص خاص طور پر ممتاز اور معزز سمجھے جاتے تھے.چنانچہ عبداللہ بن
ابی بن سلول رئیس خزرج کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ وہ کس طرح شروع میں تو اسلام سے الگ الگ رہا مگر
بعد میں بظاہر مسلمان ہو گیا، لیکن در پردہ وہ اسلام کا دشمن رہا اور منافقین مدینہ کا سردار بن گیا.دوسرا شخص
در
ابو عامر تھا جو قبیلہ اوس کا رئیس تھا.یہ شخص اپنی زندگی کے ابتدائی حصہ میں ایک سیاح رہ چکا تھا اور بہت سے
ممالک میں سفر کرنے کے بعد اب گویا تارک الدنیا ہو کر راہب کہلاتا تھا.ابو عامر کچھ کچھ نصرانیت کی
طرف مائل تھا اور ایک آزاد مذہبی معلم ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس نے
آپ کی مخالفت شروع کی اور بالآخر اپنے بغض و حسد میں جلتا ہوا مد ینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف چلا گیا اور اس
کے ساتھ وہ چند لوگ بھی جو اس کے زیر اثر تھے مدینہ چھوڑ گئے.جنگ اُحد میں ابو عامر مکہ والوں کی طرف
سے ہوکر میدان جنگ میں آیا اور قدرت حق کا عجیب نظارہ ہے کہ اسی جنگ میں اس کا لڑکا نظلہ جو ایک
نہایت مخلص مسلمان تھا، مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا.ابو عا مر فتح مکہ تک مکہ میں ہی مقیم رہا
اور فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا اور جب طائف بھی صحابہ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا تو وہ مسلمانوں کے خلاف
رومی سلطنت کے ساتھ سازش کرنے کی نیت سے شام کی طرف نکل گیا لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ
ہوسکا.ابو عا مر جب مدینہ میں تھا تو طعن و تحقیر کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرید و وحید ( یعنی
وطن سے نکالا ہوا اکیلا چھوڑا ہوا شخص ) کہہ کر پکارا کرتا تھا لیکن آخر خود اس کا یہ انجام ہوا کہ بالآخر و ہیں
شام میں وہ بے وطنی اور بے کسی و بے بسی کی حالت میں بھٹکتا ہوا مر گیا.: بخاری تفسیر سورۃ جمعہ صفحہ ۷۲۷ مطبع مجتبائی دہلی
: زرقانی خمیس جلد ۲ صفحه ۱۴۴.میور صفحه ۱۷۴.مارگولیس صفحه ۴۲۴
Page 324
۳۰۹
مواخات انصار و مہاجرین اس وقت مدینہ کے مسلمان دوحصوں میں منقسم تھے.ایک تو وہ تھے جو
مدینہ کے باشندے نہ تھے بلکہ مکہ یاکسی اور جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ
میں آباد ہو گئے تھے.یہ لوگ بوجہ اپنی ہجرت کے مہاجرین کہلاتے تھے.دوسرے وہ لوگ تھے جو مدینہ کے
رہنے والے تھے اور چونکہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مہاجرین کو پناہ دی تھی
اور ان کی اعانت کا بیڑا اٹھایا تھا اس لئے وہ انصار کے نام سے موسوم ہوتے تھے.مہاجرین عام
طور پر مدینہ میں بالکل بے سروسامان تھے کیونکہ غریب تو غریب تھے ہی متمول مہاجرین بھی عموماً اپنا سب
مال و متاع وطن میں چھوڑ کر نکل آئے تھے.انصار نے ان کے ساتھ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا
اور کوئی دقیقہ ان کی مہمان نوازی کا اٹھا نہیں رکھا.لیکن اس رشتہ اخوت کو اور بھی مضبوط کرنے کے لئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز فرمائی کہ انس بن مالک کے مکان پر انصار ومہاجرین کو جمع
فرمایا اور با ہم مناسبت کوملحوظ رکھتے ہوئے دو دو کا جوڑا بنا کر انصار و مہاجرین کے کم و بیش نوے اشخاص کے
درمیان با قاعده رشته اخوت قائم کر دیا.اس سلسلہ موافاة پر طرفین کی طرف سے جس محبت اور اخلاص
اور وفاداری کے ساتھ عملدرآمد ہوا وہ آجکل کی حقیقی اخوت کو بھی شرماتا ہے.انصار ومہاجرین بھائی بھائی
کیا بنے گویا ایک جان دو قالب ہو گئے.پہلی تجویز انصار نے اس رشتہ اخوت کے بعد یہ کی کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے باغات کو ہم میں اور
ہمارے بھائیوں میں تقسیم فرما دیں.لیکن چونکہ مہاجرین عموماً تجارت پیشہ تھے اور کھیتی باڑی کے کام سے
قطع نا واقف تھے بلکہ مکہ والے تو اس کام کو پسند بھی نہیں کرتے تھے ، اس لئے پھر انصار نے خود ہی یہ تجویز
پیش کی کہ باغات کا انتظام اور محنت ہم کریں گے ، مگر ماحصل میں سے مہاجرین کو حصہ مل جایا کرے.چنا نچہ اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا حتی کہ آہستہ آہستہ مہاجرین کی تجارتیں جن میں وہ مدینہ میں آکر مشغول
ہو گئے تھے چل نکلیں اور ان کی اپنی جائیداد میں بھی بن گئیں اور انصار کی طرف سے امداد کی ضرورت نہ
رہی ہے لکھا ہے کہ جب مہاجرین نے انصار کی طرف سے اس غیر معمولی لطف و شفقت کو دیکھا تو انہوں
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انصار کے اس سلوک کی بہت تعریف کی اور کہا کہ
یا رسول اللہ انصار کی اس نیکی کو دیکھ کر ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں خدا سے سارا اجر وہی نہ لے جائیں.آپ نے
فرمایا.نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا جب تک تم ان کی نیکی کے شکر گزار اور خدا کے حضور ان کے لئے دست بدعا
ل : بخاری باب الحجرت و نیز دیکھو مسلم کتاب الجہاد باب رد المہاجرین الی الانصار سے : مسلم باب مذکور
Page 325
۳۱۰
رہو گے تم اجر سے
محروم نہیں ہو سکتے.حضرت عبدالرحمن بن عوف سعد بن الربیع انصاری کے بھائی بنے
تھے سعد نے اپنا سارا مال و متاع نصف گن گن کر عبدالرحمن بن عوف کے سامنے رکھ دیا اور جوش محبت میں
یہاں تک کہہ دیا کہ میری دو بیویاں ہیں.میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور پھر اس کی
عدت گزرنے پر تم اس کے ساتھ شادی کر لینا.یہ سعد کی طرف سے جوش محبت کا ایک بے اختیاری
اظہار تھا.ورنہ وہ اور عبدالرحمن دونوں جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہوسکتا.چنانچہ عبدالرحمن بن عوف نے ان کا
شکر یہ ادا کیا اور ان کے لئے دعا کرتے ہوئے کہا کہ خدا یہ سب کچھ تمہیں مبارک کرے.مجھے بازار کا رستہ
بتا دو.چنانچہ عبدالرحمن بن عوف نے تجارت شروع کی اور چونکہ وہ نہایت ہوشیار اور سمجھ دار آدمی
تھے.آہستہ آہستہ ان کی تجارت چمک اٹھی اور بالآخر وہ ایک نہایت امیر کبیر آدمی بن گئے.ابھی ان کی
تجارت ابتدائی حالت میں ہی تھی اور انہیں مدینہ میں آئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ انہوں نے مدینہ کی
ایک انصاری لڑکی سے شادی کر لی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر زعفران کا رنگ دیکھا
جو عرب دستور کے مطابق شادی کی علامت سمجھا جاتا تھا.تو مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا.” ابن عوف
یہ کیا ماجرا ہے؟ عبد الرحمن نے عرض کیا.یا رسول اللہ ! میں نے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے.“ آپ
نے پوچھا.”مہر کیا دیا ہے؟ عبد الرحمن نے جواب دیا.'یا رسول اللہ ! کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا
ہے.آپ نے فرمایا.اَولِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ تو اب پھر ولیمہ کی دعوت کرنی ہوگی خواہ صرف ایک بکری کے
گوشت کی کیوں نہ ہو.یعنی اب تمہاری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ ایک دو دوستوں کو کھانا کھلا کر سمجھو کہ
بس ولیمہ ہو گیا بلکہ کم از کم ایک بکری کے اندازہ کا گوشت تو دعوت میں پکنا چاہئے.اس سلسلہ مواخات
کا اثر وراثت تک پر تھا.چنانچہ یہ فیصلہ تھا کہ اگر کوئی انصاری فوت ہو تو اس کا ترکہ بحصہ رسدی اس کے
بھائی مہاجر کو بھی ملے.یہ سمجھوتہ جنگ بدر تک قائم رہا جس کے بعد یہ طریق وراثت خدا کی وحی کے
ماتحت منسوخ ہو گیا اور صرف حقیقی رشتہ دار وارث قرار دئے گئے.اس سلسلہ مواخات میں حضرت ابوبکر
خارجہ بن زید کے بھائی بنے ، حضرت عمر عتبان بن مالک کے، حضرت عثمان اوس بن ثابت کے،
ابوعبيدة بن الجراح سعد بن معاذ کے، سعید بن زید ابی بن کعب کے سلمان فارسی ابودرداء کے،
مصعب بن عمیر ابوایوب انصاری کے ، عمار بن یاسر حذیفہ بن یمان کے.وغیر ذالک
مواخات کا یہ سلسلہ کئی لحاظ سے مفید اور بابرکت ہوا.: ابوداؤد
: بخاری باب فضائل اصحاب النبی ۳ : زرقانی ذکر موافاة
Page 326
۳۱۱
اول: جو پریشانی اور بے اطمینانی مہاجرین کے دلوں میں اس بے وطنی و بے سروسامانی کی حالت میں
پیدا ہو سکتی تھی وہ اس سے بڑی حد تک محفوظ ہو گئے.:دوم رشتہ داروں اور عزیزوں سے علیحدگی کے نتیجہ میں جس تکلیف کے پیدا ہونے کا احتمال تھا.وہ ان
نئے روحانی رشتہ داروں کے مل جانے سے جو جسمانی رشتہ داروں کی نسبت بھی زیادہ محبت کرنے
والے اور زیادہ وفادار تھے پیدا نہ ہوئی.سوم: انصار و مہاجرین کے درمیان جو محبت و اتحاد مذہبی اور سیاسی اور تمدنی لحاظ سے ان ایام میں ضروری
تھا وہ مضبوط ہو گیا.چہارم : بعض غریب اور بے کار مہاجرین کے لئے ایک سہارا اور ذریعہ معاش پیدا ہو گیا.مدینہ کی سوسائٹی کی تقسیم اور یہود کے ساتھ معاہدہ یہ بتایا جاچکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مدینہ کی آبادی
دو حصوں میں منقسم تھی.ایک تو بت پرست تھے جو قبائل اوس و خزرج میں منقسم تھے اور دوسرے یہود تھے
جن کے تین قبائل کا ذکر اوپر گزر چکا ہے.اسلام کی آمد نے ایک تیسری جماعت مسلمانوں کی پیدا کردی
اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کی آبادی میں ایک اور
فرقہ کا اضافہ ہوگیا جو منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجو د مبارک
ایک آسمانی بارش کے طور پر تھا.جس کے نتیجہ میں زمین سے ہرقسم کی اچھی بُری روئیدگی نمودار ہونی
شروع ہو جاتی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ کی مسلمان آبادی بھی دوشاخوں
میں منقسم ہو گئی اور مہاجرین و انصار کی اصطلاح کا آغاز ہو گیا.اب گویا مدینہ میں مندرجہ ذیل فرقوں کا
وجود پایا جاتا ہے.اوّل: مسلمان جو دو شاخوں میں منقسم تھے.(الف) مہاجرین جو عموماً مکہ کے رہنے والے تھے اور جو کفار کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے وطن سے
نکل آئے تھے.(ب) انصار جو مدینہ کے باشندے تھے اور جنہوں نے اسلام اور بانی اسلام کی مدد اور حفاظت کا بیڑا
اٹھایا تھا.یہ لوگ قریباً سب کے سب اوس و خزرج کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے.دوم منافقین یعنی اوس و خزرج کے وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے مگر دل میں کافر تھے اور
Page 327
۳۱۲
اسلام اور بانی اسلام کے خلاف خفیہ کاروائیاں کرتے رہتے تھے نیز ایسے لوگ بھی اسی گروہ
میں شامل سمجھے جاتے تھے جو ویسے تو ایمان لے آئے تھے مگر ان کی عملی حالت عموماً غیر مومنانہ
تھی اور غیروں کے ساتھ ان کے تعلقات بھی اسی طرح قائم تھے.سوم: بت پرست یعنی اوس وخزرج کے وہ لوگ جو ابھی تک شرک پر قائم تھے.چہارم : یہود جو قبائل بنو قینقاع، بنونضیر اور بنو قریظہ میں منقسم تھے.ان چار فرقوں میں سے پہلے فرقہ کی دونوں شاخیں پورے طور پر ایک نقطہ پر جمع تھیں کیونکہ ہرامر میں
ان کی آنکھیں ایک ہی وجود کی طرف اٹھتی تھیں اور گو عادات واطوار میں ان کا رنگ ڈھنگ مختلف تھا اور
عرب کے قدیم دستور اور رسم ورواج کے مطابق ان کا ایک نقطہ پر جمع ہونا آسان کام نہ تھا، لیکن اسلام کی
تعلیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقناطیسی شخصیت نے دوسرے سب جذبات کو دبا دیا تھا.دوسرا گروہ
جو منافقین کا تھا وہ ایک نہایت خطرناک گروہ تھا.یہ لوگ ظاہر میں مسلمان تھے مگر دل میں اسلام کے سخت
دشمن تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور حسد کی آگ سے جلے جاتے تھے.ان کی خفیہ
ریشہ دوانیوں اور مخفی شرارتوں نے اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کئی موقعوں پر نہایت
خطرناک حالات پیدا کر دئے مگر چونکہ یہ لوگ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
متبعین میں اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، اس لئے انہیں بہر حال مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا پڑتا
تھا.اور وہ اس بات پر مجبور تھے کہ کم از کم ظاہری طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو اپنے اوپر
تسلیم کریں.تیسرا گروہ ، بت پرستوں کا تھا.یہ لوگ ہجرت کے وقت تک تو کافی تعداد میں تھے مگر اس کے
بعد ان کی تعداد جلد جلد کم ہوتی گئی اور تھوڑے عرصہ میں ہی مدینہ کا شہر شرک کے عنصر سے بالکل پاک
ہو گیا.یہ لوگ گومذ ہباً مسلمان نہ تھے لیکن عرب کے تمدن کے ماتحت وہ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے
تھے کہ اپنے کثیر التعداد مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر رہیں.پس سیاسی طور پر یہ گروہ بھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے تھا اور آپ کی حکومت کو تسلیم کرتا تھا مگر چوتھا گر وہ جو یہود پر مشتمل
تھا وہ ہر طرح آزاد اور خود مختار تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش طبیعت سے یہ بعید تھا کہ آپ
ایسے حالات میں جبکہ شہر کا امن اور مسلمانوں کے جان و مال معرض خطر میں تھے اور پھر قریش کی عداوت کی
وجہ سے اسلام کی موت اور زندگی کا سوال سامنے تھا ان یہود کو مدینہ میں بغیر کسی معاہدہ کے چھوڑ
دیتے.چنانچہ ابھی ہجرت پر بہت تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ آپ نے ایک طرف مہاجرین اور اوس وخزرج
Page 328
۳۱۳
اور دوسری طرف یہود کے عمائد کو جمع کر کے ان کے سامنے اس ضرورت کو بیان کیا کہ مدینہ کی مختلف اقوام
کے درمیان ایک باہمی معاہدہ ہو جانا چاہئے جس کے ماتحت آئندہ شہر کے امن اور اس کے مختلف الاقوام
باشندوں کی حفاظت اور بہبودی کا انتظام ہو سکے اور کوئی صورت جھگڑے اور امن شکنی کی پیدا نہ ہو.چنانچہ
پہلے تو آپ نے مسلمانوں اوس اور خزرج کے اندرونی نظم ونسق کے متعلق چند قواعد فیصلہ فرمائے
اور پھر اتفاق رائے سے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ طے فرمایا جو با ضابطہ ضبط تحریر میں لایا گیا.یہ معاہدہ
جس کی طرف احادیث اور قرآن شریف میں بھی اشارہ آتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ میں درج ہے
اور اس جگہ ہم اس کی موٹی موٹی شرطیں اپنے الفاظ میں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں.مسلمان اور یہودی آپس میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف
-1
-
زیادتی یا ظلم سے کام نہیں لیں گے.ہر قوم کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی.تمام باشندگان کی جانیں اور اموال محفوظ ہوں گے اور ان کا احترام کیا جائے گا.سوائے اس کے
کہ کوئی شخص ظلم یا جرم کا مرتکب ہو.ہر قسم کے اختلاف اور تنازعات رسول اللہ کے سامنے فیصلہ کے لئے پیش ہوں گے اور ہر فیصلہ
خدائی حکم (یعنی ہر قوم کی اپنی شریعت ) کے مطابق کیا جائے گا.-۵- کوئی فریق بغیر اجازت رسول اللہ جنگ کے لئے نہیں نکلے گا.اگر یہودیوں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تو وہ ایک دوسرے کی امداد میں
کھڑے ہوں گے.-
ے.اسی طرح اگر مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے.قریش مکہ اور ان کے معاونین کو یہود کی طرف سے کسی قسم کی امداد یا پناہ نہیں دی جائے گی.-^
-9
- 1+
ہر قوم اپنے اپنے اخراجات خود برداشت کرے گی.اس معاہدہ کی رو سے کوئی ظالم یا آئم یا مفسد اس بات سے محفوظ نہیں ہوگا کہ اسے سزادی جاوے
یا اس سے انتقام لیا جاوے لے
اس معاہدہ کی رو سے مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی تعلقات منضبط ہو گئے اور مدینہ میں ایک قسم
لے: سیرۃ ابن ہشام جلد اصفحه ۱۷۹،۱۷۸
Page 329
۳۱۴
کی منظم حکومت کی بنیاد قائم ہوگئی جس کے ماتحت ہر قوم با وجود اپنے مذہب اور اپنے اندرونی معاملات میں
آزاد ہونے کے ایک اجتماعی قانون اور مرکزی حکومت کے ماتحت آگئی اور اس مرکزی حکومت کے صدر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے.مشرکین مدینہ کے نام قریش مکہ کا تہدیدی خط ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں
تشریف لائے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ
قریش مکہ کی طرف سے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس قبیلہ خزرج اور اس کے مشرک رفقاء کے نام ایک
تهدیدی خط آیا کہ تم لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پناہ سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں
ہے.چنانچہ اس خط کے الفاظ یہ تھے.إِنَّكُمُ اوَيْتُمُ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نَقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ اَوْ تُخْرِجَنَّهُ أَوْلَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا
حَتَّى نَقْتُلَ مَقَاتِلَتَكُمْ وَنَستَبِيحَ نِسَاءَ كُمْ
یعنی ” تم لوگوں نے ہمارے آدمی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پناہ دی ہے اور ہم خدا کی قسم
کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے خلاف جنگ کرو یا کم از کم اسے اپنے
شہر سے نکال دو ورنہ ہم اپنا سارا لاؤ لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور تمہارے سارے.مردوں کو تہ تیغ کر دیں گے اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے لئے جائز کر لیں گے.جب یہ خط مدینہ میں پہنچا تو عبداللہ اور اس کے ساتھی جو پہلے سے ہی دل میں اسلام کے سخت دشمن
ہورہے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے.آپ کو اطلاع ملی تو
آپ فوراً ان لوگوں سے ملے اور ان کو سمجھایا کہ میرے ساتھ جنگ کرنے میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے
کیونکہ تمہارے ہی بھائی بند تمہارے مقابلہ میں ہوں گے یعنی اوس اور خزرج کے مسلمانوں نے بہر حال
میرا ساتھ دینا ہے.پس میرے ساتھ جنگ کرنے کے صرف یہ معنے ہوں گے کہ تم لوگ اپنے ہی بیٹوں اور
بھائیوں اور باپوں کے خلاف تلوار اٹھاؤ.اب تم خود سوچ لو " عبد اللہ اور اس کے ساتھیوں کو جن کے
دلوں میں ابھی تک جنگ بعاث کی تباہی کی یاد تازہ تھی یہ بات سمجھ آگئی اور وہ اس ارادے سے باز آ گئے ہے
جب قریش کو اس تدبیر میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے کچھ عرصہ کے بعد اور اسی قسم کا ایک خط مدینہ کے یہود
کے نام ارسال کیا.مگر اس کا ذکر آگے چل کر اپنے وقت پر آئے گا.دراصل کفار مکہ کی غرض یہ تھی کہ جس
ل : ابوداؤد کتاب الخراج باب في خبر النفير
: ابو داؤد باب في النفير
Page 330
۳۱۵
طرح بھی ہو اسلام کے نام و نشان کو صفحہ دنیا سے مٹا دیا جاوے.مسلمان ان کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ
گئے تو وہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور اس بات کی کوشش میں اپنی انتہائی طاقت صرف کر دی کہ نیک دل
نجاشی ان مظلوم غریب الوطنوں کو مکہ والوں کے حوالے کر دے.پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے
ہجرت کر کے مدینہ آگئے تو قریش نے آپ کا تعاقب کر کے آپ کو گرفتار کر لینے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں
رکھا اور اب جب انہیں یہ علم ہوا کہ آپ اور آپ کے اصحاب مدینہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں اسلام سرعت کے
ساتھ پھیل رہا ہے تو انہوں نے یہ تہدیدی خط بھیج کر مدینہ والوں کو آپ کے ساتھ جنگ کر کے اسلام کو
ملیا میٹ کر دینے یا آپ کی پناہ سے دستبردار ہو کر آپ کو مدینہ سے نکال دینے کی تحریک کی.قریش کے اس
خط سے عرب کی اس رسم پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ وہ جنگوں میں اپنے دشمنوں کے سارے مردوں کو قتل کر کے
ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے اور پھر ان کو اپنے لئے جائز سمجھتے تھے اور نیز یہ کہ مسلمانوں کے متعلق ان
کے ارادے اس سے بھی زیادہ خطر ناک تھے.کیونکہ جب یہ سزا انہوں نے مسلمانوں کے پناہ دینے والوں
کے لئے تجویز کی تھی تو خود مسلمانوں کے لئے تو یقیناً وہ اس سے بھی زیادہ سخت ارادے رکھتے ہوں گے.ابو جہل کی دھمکی قریش مکہ کا یہ خط ان کے کسی عارضی جوش کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وہ مستقل طور پر اس بات
کا تہیہ کر چکے تھے کہ مسلمانوں کو چین نہیں لینے دیں گے اور اسلام کو دنیا سے مٹاکر
چھوڑیں گے.چنانچہ ذیل کا تاریخی واقعہ قریش مکہ کے خونی ارادوں کا پتہ دے رہا ہے.بخاری میں روایت آتی ہے کہ ہجرت کے کچھ عرصہ بعد سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے
اور مسلمان ہو چکے تھے عمرہ کے خیال سے مکہ گئے اور اپنے زمانہ جاہلیت کے دوست امیہ بن خلف رئیس مکہ
کے پاس مقیم ہوئے.چونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ والے ان کے ساتھ ضرور چھیڑ چھاڑ کریں گے اس لئے
انہوں نے فتنہ سے بچنے کے لئے امیہ سے کہا کہ میں کعبتہ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ
ہوکرایسے وقت میں مجھے طواف کرا دو جبکہ میں علیحدگی میں امن کے ساتھ اس کام سے فارغ ہو کر اپنے وطن
واپس چلا جاؤں.چنانچہ امیہ بن خلف دو پہر کے وقت جبکہ لوگ عموماً اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں
سعد کو لے کر کعبہ کے پاس پہنچا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ابو جہل بھی وہاں آنکلا اور جونہی اس
کی نظر سعد پر پڑی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا مگر اپنے غصہ کو دبا کر وہ امیہ سے یوں مخاطب ہوا کہ ”اے
ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے امیہ نے کہا.” یہ سعد بن معاذ رئیس اوس ہے.“ اس پر ابو جہل
نہایت غضبناک ہو کر سعد سے مخاطب ہوا کہ ” کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ اس مرتد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )
Page 331
۳۱۶
کو پناہ دینے کے بعد تم لوگ امن کے ساتھ کعبہ کا طواف کر سکو گے اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اس کی
حفاظت اور امداد کی طاقت رکھتے ہو؟ خدا کی قسم اگر اس وقت تیرے ساتھ ابو صفوان نہ ہوتا تو تو اپنے
گھر والوں کے پاس بیچ کر نہ جاسکتا؟ سعد بن معاذ فتنہ سے بچتے تھے مگر ان کی رگوں میں بھی ریاست کا
خون تھا اور دل میں ایمانی غیرت جوش زن تھی.کڑک کر بولے ”واللہ اگر تم نے ہم کو کعبہ سے روکا تو یا درکھو
کہ پھر تمہیں بھی تمہارے شامی راستے پر امن نہیں مل سکے گا.امیہ نے کہا ”سعد! دیکھو ابوالحکم سید اہل وادی
کے مقابلہ میں یوں آواز بلند نہ کرو.سعد نے جواب دیا ” جانے دو امیہ ! تم اس بات میں نہ آؤ.واللہ
مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نہیں بھولتی کہ تم کسی دن مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہو گے.یہ خبر
سن کرامیہ بن خلف سخت گھبرا گیا اور گھر میں آکر اس نے اپنی بیوی کو سعد کی اس بات سے اطلاع دی اور
کہا کہ خدا کی قسم میں تو اب مسلمانوں کے خلاف مکہ سے نہیں نکلوں گا مگر تقدیر کے نوشتے پورے ہونے
تھے.بدر کے موقع پر امیہ کو مجبوراً مکہ سے نکلنا پڑا اور وہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہوکر اپنے
کیفر کردار کو پہنچا.یہ امیہ وہی تھا جو حضرت بلال پر اسلام کی وجہ سے نہایت سخت مظالم کیا کرتا تھا.ولید بن مغیرہ کی موت اور قریش کے خونی ارادے پھر اسی زمانہ کی بات ہے کہ خالد بن ولید
کا والد ولید بن مغیرہ جو مکہ کا ایک نہایت
با اثر اور معزز رئیس تھا بیمار ہو گیا اور جب اس نے دیکھا کہ اب اس کی موت قریب ہے تو وہ بے اختیار سا
ہو کر رونے لگ گیا اس وقت مکہ کے بعض بڑے بڑے رئیس اس کے پاس بیٹھے تھے.انہوں نے حیران
ہو کر اس کے رونے کا سبب پوچھا تو ولید نے کہا ” کیا تم سمجھتے ہو کہ میں موت کے ڈر سے روتا ہوں.واللہ
ایسا ہر گز نہیں.مجھے تو یہ غم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین پھیل جائے اور مکہ بھی اس
کے قبضہ میں چلا جائے.ابوسفیان بن حرب نے جواب دیا کہ اس بات کا غم نہ کرو.جب تک ہم زندہ
ہیں ایسا نہیں ہوگا ، ہم اس بات کے ضامن ہوتے ہیں.مدینہ میں خوف کی راتیں یہ تمام باتیں قریش مکہ کے ان خونی ارادوں کا پتہ دے رہی ہیں جو وہ
ہجرت کے بعد اسلام کے متعلق رکھتے تھے اور مسلمان ان ارادوں سے
،،
ناواقف نہ تھے بلکہ خوب سمجھتے تھے کہ مکہ والوں کے یہ بدلے ہوئے تیور عنقریب کوئی رنگ لائیں گے
اور گوان کو خدا کے وعدوں پر پورا بھروسہ تھا لیکن فطرتاً وہ سخت خوفزدہ اور پریشان بھی تھے کہ دیکھئے ہمیں
: بخاری کتاب المغازی
۲ : تاریخ الخمیس جلد اصفحه ۳۹۸
Page 332
۳۱۷
کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے.شروع شروع میں تو یہ خوف ایسا غالب تھا کہ صحابہ کو مدینہ میں
رات کے وقت نیند نہیں آتی تھی کہ نہ معلوم کس وقت ان پر کوئی حملہ ہو جاوے اور یہ خطرات طبعاً
دوسرے مسلمانوں کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زیادہ تھے اور چونکہ ویسے بھی آپ کوسب
کی نسبت مسلمانوں کی حفاظت کا زیادہ فکر تھا اس لئے آپ سب سے زیادہ محتاط تھے.چنانچہ نسائی میں
ایک روایت آتی ہے کہ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَوَّلُ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ يَسْهَرُ
مِنَ الَّيلِ یعنی جب شروع شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ
عمو ماراتوں کو جاگتے رہتے تھے.اور اسی مضمون کی ایک روایت بخاری اور مسلم کے میں ہے کہ ارق
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرِسُنِي
اللَّيْلَةَ إِذَا سَمِعْنَا صَوْتَ السّلَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا قَالَ
سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ يَارَسُولَ اللهِ جِئْتُ اَحْرَسَكَ فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - یعنی
ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک جاگتے رہے اور پھر فرمایا کہ اگر اس وقت ہمارے
دوستوں میں سے کوئی مناسب آدمی پہرہ دیتا تو میں ذرا سولیتا.اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار
سنی.آپ نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی.یا رسول اللہ ! میں سعد بن ابی وقاص ہوں.میں اس لئے حاضر
ہوا ہوں کہ پہرہ دوں.اس اطمینان کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لئے سو گئے.اور مسلم کے اسی باب کی
دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ابتدائے ہجرت کا ہے.یادرکھنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ
فکر اپنی ذات کے متعلق نہ تھا بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا فکر تھا اور ان خوف کے ایام میں آپ یہ
ضروری خیال فرماتے تھے کہ مدینہ میں رات کے وقت پہرہ کا انتظام رہے چنانچہ اس غرض سے بسا اوقات
آپ خود رات کو جا گا کرتے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ہوشیار و چوکس رہنے کی تاکید فرماتے تھے اور آپ
کا یہ فکر ڈریا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ احتیاط اور بیدار مغزی کی بناء پر تھا.ورنہ آپ کی ذاتی شجاعت
اور مردانگی تو دوست و دشمن میں مسلم ہے.چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک رات مدینہ میں کچھ شور ہوا اور
لوگ گھبرا کر گھروں سے نکل آئے اور جس طرف سے شور کی آواز آئی تھی ادھر کا رخ کیا.ابھی وہ تھوڑی دور
ہی گئے تھے کہ سامنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلوار حمائل کئے ابوطلحہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار
واپس تشریف لا رہے تھے.جب آپ قریب آئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا.”میں دیکھ آیا ہوں کوئی فکر
ل : دیکھو فتح الباری جلد ۶ صفحه۶۰
: کتاب التمنی سے : باب فضل سعد بن ابی وقاص
Page 333
۳۱۸
کی بات نہیں ، کوئی فکر کی بات نہیں.جس پر لوگ واپس لوٹ آئے.ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس رات
بھی آپ جاگ رہے تھے اور جو نہی آپ نے شور کی آواز سنی آپ گھٹ ابوطلحہ والے گھوڑے پر سوار ہو کر
اس طرف نکل گئے اور لوگوں کے روانہ ہوتے ہوتے پتہ لے کر واپس بھی آگئے.قبائل عرب
کی متحدہ مخالفت اور مسلمانوں کی نازک حالت قریش مکہ کے جن خونی
ارادوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے
وہ صرف انہیں تک محدود نہ تھے بلکہ ہجرت کے بعد سے انہوں نے قبائل عرب میں مسلمانوں کے خلاف
ایک باقاعدہ پراپیگنڈہ جاری کر رکھا تھا اور چونکہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کا سارے عرب پر
ایک گہرا اثر تھا ، اس لئے ان کی اس انگیخت سے تمام عرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت
دشمن ہورہا تھا.قریش کے قافلوں نے تو گویا اپنا یہ فرض قرار دے رکھا تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے راستہ میں
قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے.چنانچہ قرآن شریف میں قریش کے ان اشتعال
انگیز دوروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.بیچارے مسلمان جو اس وقت تک صرف قریش کے خیال سے ہی
سہمے جاتے تھے اب بالکل ہی سراسیمہ ہونے لگے.چنانچہ حاکم اور طبرانی کی مندرجہ ذیل روایت ان کی
اس وقت کی مضطر بانہ حالت کا پتہ دیتی ہے.لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ الْمَدِينَةَ وَاوَتْهُمُ الْأَنْصَارُ رَمَتْهُمُ
الْعَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ وَكَانُوا لَا يَبِيتُونَ إِلَّا بِالسَّلَاحِ وَلَا يَصْبَحُونَ إِلَّا فِيْهِ وَكَانُوا يَقُولُونَ
اَلَا تَرَوْنَ أَنَّا نَعِيْشُ حَتَّى نَبِبَيْتُ امِنِينَ مُطْمَئِنِينَ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ
د یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور
انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب ایک جان ہو کر ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا.اس وقت
مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ رات کو بھی ہتھیار لگا کر سوتے تھے اور دن کو بھی ہتھیار لگائے رہتے
تھے کہ کہیں کوئی اچانک حملہ نہ ہو جاوے اور وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھئے ہم
اس وقت تک زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں جب ہم رات کو امن کی نیند سوسکیں گے اور سوائے
خدا کے ہمیں اور کسی کا ڈر نہ ہوگا.“
: مسلم کتاب الفصائل باب فی شجاعة النبی صلی اللہ علیہ وسلم : سورة آل عمران : ۱۹۷
: حاکم بحوالہ لُبَابُ التَّقُولِ فِي أَسْبَابِ النُّزُول زیرآیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَنُوا مِنْكُمْ
Page 334
۳۱۹
قرآن شریف نے جو مخالفین اسلام کے نزدیک بھی اسلامی تاریخ کا سب سے زیادہ مستند ریکارڈ ہے
مسلمانوں کی اس حالت کا مندرجہ ذیل الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے.وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَفَكُمُ
النَّاسُ فَاوِيكُمْ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الظَّيْبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَO
یعنی اے مسلمانو! وہ وقت یاد رکھو جبکہ تم ملک میں بہت تھوڑے اور کمزور تھے اور تمہیں
ہر وقت یہ خوف لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اُچک کر لے جائیں یعنی اچانک حملہ کر کے
تمہیں تباہ نہ
کرد میں مگر خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری مددفرمائی اور تمہارے لئے پاکیزہ
نعمتوں کے دروازے کھولے.پس تمہیں اب شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہئے.“
سچ ہے اگر اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہوتی تو اس زمانہ میں مسلمانوں کی حالت واقعی ایسی نازک
ہو رہی تھی کہ ظاہری اسباب کے ماتحت ان کی زندگی کے دن بہت محدود نظر آتے تھے.بیشک مکہ میں بھی
ان کے لئے مصائب تھے اور سخت مصائب تھے اور انہیں دن رات قریش کے بے دردانہ مظالم کا تختہ مشق
بن کر رہنا پڑتا تھا لیکن مدینہ میں ان کی حالت شروع شروع میں کئی لحاظ سے زیادہ نازک اور زیادہ
خطرناک ہوگئی تھی، کیونکہ مکہ میں صرف قریش کی طرف سے اندیشہ تھا اور قریش کے متعلق مسلمانوں کو ایک
حد تک یہ اطمینان تھا کہ خواہ ان کی مخالفت کیسی بھی سخت صورت اختیار کرے جب تک مسلمان مکہ میں ہیں
قبائل کے باہمی تعلقات کا خیال قریش کو اس بات سے باز رکھے گا کہ وہ ایک جتھے کی صورت میں
مسلمانوں پر حملہ آور ہوکر بلاتمیز سب کو تہ تیغ کردیں.مختلف قبائل کی باہمی رقابتیں رشتہ داری کے
احساسات وغیرہ کئی اس قسم کی باتیں تھیں جو عموما قریش کو مسلمانوں کے خلاف ہاں کم از کم معزز خاندانوں
سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے خلاف انتہائی کاروائی کرنے سے باز رکھتی تھیں.چنانچہ یاد ہوگا کہ
انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کس قدر طویل بحث و تامل کے بعد اور پھر کتنی
احتیاطوں کے ساتھ اختیار کیا تھا، لیکن اب ہجرت کے بعد نہ صرف یہ کہ قریش مکہ کی مخالفت بہت زیادہ
چمک گئی تھی اور اس خیال نے کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے ہیں اور غیروں کے ہاں پناہ گزیں
ہوئے ہیں ان کے بغض و عداوت کی آگ کو خطرناک طور پر بھڑکا دیا تھا.بلکہ عرب کے دوسرے قبائل بھی
ایک جان ہو کر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور خود مدینہ کے شہر میں ایسے منافقین موجود
ا : سورۃ الانفال: ۲۷
Page 335
۳۲۰
تھے جو مخالفین کے ہاتھ میں مسلمانوں کے خلاف ایک نہایت کارگر ہتھیار کا کام دے سکتے تھے اور یہود کا
وجود مزید براں خطرے کے احتمالات پیدا کر رہا تھا اور ان خطرات کے مقابلہ میں انصار کی جمعیت کچھ بھی
حقیقت نہیں رکھتی تھی.ان حالات میں گو مسلمانوں کو خدا کے وعدوں پر بھروسہ تھا لیکن اس ظاہری حالت کو
دیکھ کر ان میں سے بہتوں کے دل اندر ہی اندر بیٹھے جاتے تھے اور خوف اور بے چینی کا ایسا غلبہ تھا کہ
ان بے چاروں کو رات کے وقت نیند نہیں آتی تھی.ناظرین کو چاہئے کہ ان باتوں کو اچھی طرح یا درکھیں
کیونکہ آگے چل کر انہیں باتوں نے اس جنگ عظیم کی بنیاد بننا ہے جومسلمانوں اور کفار عرب کے درمیان
وقوع میں آئی اور جس نے عرب کی وسیع سرزمین میں خون کی ندیاں بہا دیں.ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں جو پہلا بچہ مدینہ میں
ہجرت کے بعد مہاجرین کا پہلا بچہ اور
پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے اور اسی لئے ان کی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پیدائش پر مہاجرین کو بہت خوشی ہوئی عبداللہ بن زبیر
تاریخ اسلامی میں ایک بہت مشہور و معروف آدمی ہیں.ان کے والد ز بیرا بن العوام کا حال کتاب کے حصہ
اول میں گزر چکا ہے.زبیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور کبار صحابہ میں شمار ہوتے
تھے.حضرت ابو بکڑ نے اپنی لڑکی اسماء کو جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھیں زبیر کے عقد میں دیا تھا اور انہی
اسماء کے بطن سے ہجرت کے پہلے سال میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے.جس وقت عبداللہ کو اٹھا کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ نے ایک کھجور کو اپنے منہ میں نرم کر کے اس کا لعاب
عبداللہ کے منہ میں ڈالا اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اور یہی اس کی پہلی خوراک تھی.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو عبداللہ بالکل بچہ تھے لیکن بعد میں بڑے ہوکر انہوں نے اپنے علم وفضل
سے بڑارتبہ حاصل کیا.شاہان بنوامیہ کے قابل اعتراض مسلک کو دیکھ کر انہوں نے اپنی علیحدہ حکومت قائم
کر لی تھی لیکن بالآخر عبدالملک بن مروان کے عہد حکومت میں شہید ہوئے.حضرت عائشہ انہیں اپنے
بچے کے طور پر سمجھتی تھیں اور اسی لئے ان کی کنیت عبداللہ کے نام پر ام عبد اللہ مشہور ہوگئی تھی.انصار کے دور ئیسوں کی وفات ہجرت کے پہلے سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
دو مخلص اصحاب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا یعنی کلثوم بن الہدم
جن کے مکان پر آپ قبا میں قیام فرما ہوئے تھے اور جو ایک معمر آدمی تھے فوت ہو گئے اور اسی زمانہ میں
اسعد بن زرارة کا بھی انتقال ہوا.اسعدان ابتدائی چھ اشخاص میں سے تھے جنہوں نے مکہ میں بیعت
Page 336
۳۲۱
عقبہ اولیٰ سے بھی ایک سال قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور جن کے مکان پر اسلام کے
ب سے پہلے مبلغ مصعب بن عمیر نے مدینہ میں قیام کیا تھا اور جو ہجرت سے قبل مدینہ میں نماز با جماعت
اور جمعہ کا التزام کیا کرتے تھے.نیز اسعدان بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں مقرر فرمائے تھے.چنانچہ ان کی وفات پر بنو نجار نے جن کے وہ
نقیب تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ اسعد بن زرارہ کا کوئی قائم
مقام مقرر فرمایا جاوے لیکن چونکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی آپ نے فرمایا اب میں خود تمہارا نقیب ہوں
کسی اور نقیب کی ضرورت نہیں ہے
دو معاندین اسلام کی ہلاکت اسی سال اسلام کے دو نہایت ذی اثر مخالفین کی موت بھی وقوع
میں آئی ، چنانچہ ولید بن مغیرہ کی موت کا ذکر اوپر گزر چکا ہے.اسی
کے قریب مکہ میں عاص بن وائل کی موت واقع ہوئی ہے یہ دونوں شخص اسلام کے سخت مخالف تھے اور مکہ میں
نہایت عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے مگر یہ ایک عجیب منظر ہے کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ
ان مرنے والوں کی اولا د آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو کر فدایان اسلام کی
صف اول میں کھڑی نظر آتی ہے.چنانچہ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کے کارنامے تاریخ اسلام میں کسی
معترفی کے محتاج نہیں.: طبری
: طبری
Page 337
۳۲۲
جہاد بالسیف کا آغاز
اور
جہاد کے متعلق اصولی بحث
جہاد بالسیف کا آغاز اب ہم ہجرت کے دوسرے سال اور اسلامی تاریخ کے اس حصہ میں داخل
ہوتے ہیں جس میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کا آغاز ہوا.جہاد بالسیف
کا مسئلہ جس کے ماتحت مسلمانوں کی تلوار نیام سے باہر آئی باوجود در حقیقت ایک بہت صاف اور سادہ
مسئلہ ہونے کے ان متضاد خیالات کی وجہ سے جو بد قسمتی سے خود بعض مسلمانوں کی طرف سے اس کے متعلق
ظاہر کئے گئے ہیں اور نیز بعض غیر
مسلم مؤرخین کی تحریرات کی وجہ سے جو انہوں نے مؤرخ کی حیثیت سے
ہٹ کر ایک متعصب مذہبی مناظر کی حیثیت میں لکھی ہیں ایک نہایت پیچ دار مسئلہ بن گیا ہے.کہا جاتا ہے کہ
اسلام نے ابتداء تلوار کے سایہ کے نیچے پرورش پائی جو ہر اس شخص کے سر پر اٹھتی تھی جو اسلام لانے سے
انکار کرتا تھا اور مسلمانوں
کا یہ مذہبی فرض مقرر کیا گیا تھا کہ وہ تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنا ئیں.یہ خیال حقیقت سے کس قدر دور اور صحیح تاریخی واقعات کے کس قدر خلاف ہے؟ اس کا جواب ذیل کے
اوراق میں ملے گا.حقیقت حال یہ ہے اور اس حقیقت کے شواہد ابھی ظاہر ہو جائیں گے کہ اس ابتدائی
زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ابتداء جو کچھ کیا وہ دفاع اور خود حفاظتی میں کیا اور
وہ بھی اس وقت کیا جبکہ قریش مکہ اور ان کی انگیخت پر دوسرے قبائل عرب کی معاندانہ کارروائیاں اس حد کو
پہنچ چکی تھیں کہ ان سے مقابلہ میں مسلمانوں کا خاموش رہنا اور اپنی حفاظت کے لئے ہاتھ نہ اٹھانا خودکشی
کے ہم معنی تھا جسے کوئی عقل مند نظر استحسان سے نہیں دیکھ سکتا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
دفاعی جنگ کے دوران جو جو کارروائیاں فرمائیں وہ حالات پیش آمدہ کے ماتحت نہ صرف بالکل جائز اور
درست تھیں بلکہ جنگی ضابطہ اخلاق کا جو معیار آپ نے قائم فرمایا وہ آج بھی دنیا کے واسطے ایک بہترین
Page 338
۳۲۳
نمونہ ہے جس سے زیادہ بختی اور سزا کی طرف مائل ہونا عدل اور رحم کے منافی ہے اور جس سے زیادہ نرمی
اور رعایت کا طریق اختیار کرنا دنیا کے امن کے لئے سم قاتل.درحقیقت اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ فطرت
کا مذہب ہے اس لئے نہ تو وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر صورت میں ہر گناہ اور ہر جرم کی سزا ہونی چاہئے اور نہ
وہ یہ سکھاتا ہے کہ کسی حالت میں بھی بدی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ ہر دو تعلیمات افراط وتفریط کی
راہیں ہیں اور ان پر عمل کرنے سے
کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا اور نہ اقوام وافراد کے اخلاق کی اصلاح
ہوسکتی ہے اور صحیح اور بچی تعلیم یہی ہے کہ جَزَ و سَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ
على الله یعنی ”بدی اور جرم کی سزا اس کے مناسب حال ہونی چاہئے لیکن اگر عفو کرنے سے
اصلاح ہوتی ہو تو عفو کرنا چاہئے اور اس رنگ میں عفو کرنے والا شخص خدا کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا.یہ
قرآنی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی ضابطہ اخلاق کا خلاصہ ہے اور آپ کی تمام جنگی
کارروائیاں اسی آیت کی تفسیر ہیں.کیا اسلام میں مذہب کے معاملہ میں جبر کرنا جائز ہے؟ ابتدائی اسلامی لڑائیوں پر
نظر ڈالنے سے پیشتر ہمارا فرض
ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام مذہبی معاملات میں جبر کرنے کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے.یعنی کیا اسلامی تعلیم
کی رو سے یہ جائز ہے کہ لوگوں کو جبراً اسلام میں داخل کیا جاوے اور تلوار کے ذریعہ اسلام پھیلا یا جاوے.اگر اسلام جبر کی اجازت دیتا ہے تو پھر بیشک معاملہ مشتبہ ہو جائے گا.کیونکہ اس صورت میں اس بات کا
امکان ہوگا کہ شاید ابتدائی اسلامی جنگیں بھی لوگوں کو بزور مسلمان بنانے کی غرض سے کی گئی ہوں لیکن اگر
یہ ثابت ہو کہ اسلامی تعلیم کی رو سے مذہب میں جبر ممنوع ہے تو پھر یہ ایک قوی ثبوت اس بات کا ہوگا کہ یہ
ابتدائی اسلامی لڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی غرض سے نہ تھیں بلکہ ان کی وجوہات کوئی اور
تھیں
کیونکہ یہ ہرگز ممکن نہیں اور کوئی عقل مند سے قبول نہیں کر سکتا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ نے ایسے بر ملا طور پر اس تعلیم کے خلاف قدم مارا ہو جو وہ خدا کی طرف منسوب کر کے لوگوں
کو سناتے تھے اور جس پر ان کی قومی ہستی کا دارو مدار تھا.اب ہم قرآن شریف پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں صریح طور پر جبری اشاعت کے خلاف احکام پاتے
ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
: سورۃ شوری: ۴۱
Page 339
۳۲۴
قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْ مِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
اے رسول! تو کہہ دے لوگوں سے کہ یہ اسلام حق ہے تمہارے رب کی طرف سے
پھر اس کے بعد جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے.“
پھر فرماتا ہے:
قُلْ يَا يُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى
لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ o
یعنی ”اے رسول ! تو لوگوں سے کہہ دے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
حق آتا ہے پس اب جو شخص ہدایت کو قبول کرے گا تو اس کا فائدہ خود اسی کے نفس کو ہو گا اور
جو غلط راستہ پر چلے گا اس کا وبال بھی خود اسی کی جان پر ہے اور میں کوئی تمہاری ہدایت کا
ذمہ دار نہیں ہوں.“
پھر فرماتا ہے:
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْ ۚ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ
بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ :
یعنی دین کے معاملہ میں جبر نہیں ہونا چاہئے.ہدایت اور گمراہی کا معاملہ پوری طرح
کھل چکا ہے.پس اب جو شخص گمراہی کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے گا.وہ گویا ایک نہایت
مضبوط کڑے کو پکڑلے گا جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے.“
اس قرآنی آیت کی عملی تشریح میں ایک حدیث آتی ہے کہ فَلَمَّا أُجْلِيَتْ بَنُو نَضِيرٍ كَانَ فِيهِمُ
مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَى لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَى : یعنی جب بنو نضیر مدینہ سے جلا وطن کئے گئے تو ان میں وہ لوگ بھی تھے جو انصار کی
اولاد تھے.انصار نے انہیں روک لینا چاہا؟ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی آیت کے ماتحت
ا : کهف : ۳۰
ے : سورة بقرة : ۲۵۷
: سورۃ یونس : ١٠٩
: ابوداؤ د کتاب الجہاد
۵ : زمانہ جاہلیت میں جب کسی اوسی یا خزرجی مشرک کے اولادیر بینہ نہ ہوتی تھی تو وہ منت مانتا تھا کہ اگر میرے ہاں کوئی
لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے یہودی بنا دوں گا.اس طرح اوس و خزرج کے کئی بچے یہودی بن گئے تھے.
Page 340
۳۲۵
کہ دین کے معاملہ میں جبر نہ ہونا چاہئے انصار کو منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں.پھر حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت
کے متعلق وثیق رومی کی ایک روایت آتی ہے کہ كُنتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ أَسْلِمُ.....قَالَ
فَأَبَيْتُ فَقَالَ لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ اعْتَقَنِي فَقَالَ اذْهَبُ حَيْثُ شِئْتَ يَا
یعنی وثیق رومی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں میں ان کا غلام ہوتا تھا.آپ مجھ سے
فرماتے رہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ مگر میں انکار کرتا تھا اور حضرت عمر یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ اچھا
لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین کے معاملہ میں جبر جائز نہیں ہے.“ پھر جب ان کی وفات کا وقت
قریب آیا تو انہوں نے مجھے خود بخود آزاد کر دیا اور فرمایا اب جہاں چاہتے ہو چلے جاؤ.پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَالْأَمِينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَاعُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِي :
یعنی اے رسول! کہہ دے اہل کتاب اور مشرکین سے کہ کیا تم اسلام کو قبول کرتے
ہو؟ یعنی ان کو اسلام کا پیغام پہنچا دے.پھر اگر وہ اسلام کو قبول کر لیں تو جانو کہ وہ ہدایت
پاگئے، لیکن اگر وہ تیری دعوت کو رد کر دیں تو تیرا کام تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کو خود دیکھ رہا ہے.“
قرآن شریف کی یہ آیات جن کو میں نے ان کے نازل ہونے کی تاریخ کے مطابق ترتیب کے ساتھ
درج کیا ہے اس بات کا ایک قطعی ثبوت ہیں کہ اسلامی تعلیم کی رو سے دین کے معاملہ میں جبر کرنا جائز نہیں
ہے بلکہ اسلام نے دین کے معاملہ کو ہر شخص کے ضمیر پر چھوڑ دیا ہے کہ جس مذہب کو کوئی شخص اپنے لئے پسند
کرے اختیار کرے.ان آیات میں سے سورۃ کہف کی آیت مکی زمانہ کی ہے.سورۃ یونس کی آیت بعض
محققین کے نزدیک مکی زمانہ کے آخری ایام کی ہے اور بعض کے نزدیک مدنی ہے.سورۃ بقرۃ کی آیت
مدینہ کے ابتدائی سالوں کی ہے جبکہ اسلامی جنگوں کا آغاز ہوا تھا اور سورۃ آل عمران کی آیت مدینہ کے
آخری زمانہ کی ہے جبکہ مکہ اور طائف وغیرہ فتح ہو چکے تھے اور عرب کی جنگوں کا قریباً خاتمہ تھا.گویا یہ
مختلف آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف زمانوں میں نازل ہوئی تھیں اور آخری آیت
آپ کی وفات کے قریب نازل ہوئی تھی اور یہ ساری آیات قطعی اور یقینی طور پر جبری اشاعت کو ممنوع
عوارف بروایت ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء
: سورة آل عمران : ۲۱
Page 341
٣٢٦
قرار دیتی ہیں اور رسول کا صرف یہ کام بتاتی ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو کھول کھول کر لوگوں کو سنادے.آگے ماننا
نہ ماننا لوگوں کا اپنا کام ہے.اب کیا یہ ممکن ہے کہ اس صریح اور واضح تعلیم کے ہوتے ہوئے جو بانگ بلند
دن رات لوگوں کو سنائی جاتی تھی اور جس کی طرف کفار کو بلایا جاتا تھا.خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لئے تلوار ہاتھ میں لے کر نکلتے.اور پھر کیا اس صورت
میں کفار یہ اعتراض نہ کرتے کہ تم اپنے خدا کا کلام تو جبر کے خلاف سناتے ہواور خود جبر کرتے ہومگر
تاریخ سے ثابت ہے کہ کفار کی طرف سے کبھی یہ اعتراض نہیں ہوا.حالانکہ ان کی عادت تھی کہ خوب جی
کھول کھول کر آپ کے خلاف اعتراض کیا کرتے تھے اور ان کے اعتراضات قرآن کریم اور کتب حدیث
و تاریخ میں کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں.آغاز جہاد کے وقت مسلمانوں کی حالت جبر کے خیال کی مکذب ہے پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ جس وقت
مسلمانوں کی طرف سے جہاد کا آغاز ہوا اس وقت ان کی جو حالت تھی وہ بھی جبر کے خیال کو جھٹلاتی
ہے.بھلا گنتی کے چند لوگ جن کے خلاف گویا سارا ملک ہتھیار بند تھا اور جن کا یہ حال تھا کہ خوف کے
مارے ان کو رات نیند نہیں آتی تھی وہ جبر کے خیال سے جنگ شروع کر سکتے ہیں؟ ایسی حالت میں تو صرف
وہی شخص لڑائی کے لئے نکل سکتا ہے جو یا تو یہ سمجھتا ہو کہ اب موت سے بچنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو یہی ہے
کہ خود حفاظتی کے لئے تلوار نکال لی جاوے اور یا وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اب مرنا تو ہے ہی کیوں نہ مردوں کی
طرح میدان جنگ میں جان دی جاوے.ان دوغرضوں کے سوا کسی اور غرض کے لئے کوئی شخص جو مجنون
نہیں ہے اس حالت میں لڑائی کے لئے نہیں نکل سکتا جو اس وقت مسلمانوں کی تھی.اور یہ اس بات کا
ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی لڑائیاں دفاع اور خود حفاظتی کے لئے تھیں نہ کہ جبر اور تشدد کی غرض سے.کبھی کوئی شخص جبراً مسلمان نہیں بنایا گیا پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اگرآ نحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یہ لڑائیاں لوگوں کو جبراً
مسلمان بنانے کی غرض سے تھیں تو تاریخ سے ہمیں ایسے لوگوں کی مثالیں نظر آنی چاہئیں جو بزور مسلمان
بنائے گئے آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہزاروں مسلمانوں اور کافروں کے نام تاریخ میں
محفوظ ہیں کوئی ایک مثال تو ایسے شخص کی ملنی چاہئے جسے تلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو.یہ ایک
حقیقت ہے کہ تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی جبری تبلیغ کی نظر نہیں آتی.ہاں دوسری طرف ایسی مثالیں
Page 342
۳۲۷
تاریخ سے ثابت ہیں کہ عین لڑائی کے دوران میں کسی مشرک نے اسلام کا اظہار کیا لیکن مسلمانوں نے اس
خیال سے کہ یہ شخص ڈر کر اسلام کا اعلان کر رہا ہے اور اس کے اسلام کے اظہار کے ساتھ دل کی تصدیق
شامل نہیں ہے اس کے اسلام کو اسلام نہیں سمجھا اور اسے تلوار کی گھاٹ اتار دیا.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے
کہ ایک لڑائی میں اسامہ بن زید جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے
صاحبزادے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے ایک کافر کے سامنے ہوئے.جب اس کا فر
نے دیکھا کہ اسامہ نے اس پر غلبہ پالیا ہے تو کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن اسامہ نے اس کی پروا
نہ کی اور اپنا نیزہ چلا دیا.جب لڑائی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کا ذکر ہوا
تو آپ اسامہ پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جب وہ شخص اسلام کا اظہار کرتا تھا تو تم نے اسے کیوں
مارا؟ اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ! وہ ڈر کے مارے ایسا کہتا تھا اور دل میں مسلمان نہیں تھا.آپ نے
فرمایا ” کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ یعنی بالکل ممکن ہے کہ اسی وقت اس پر اسلام کی صداقت
کھل گئی ہو اور وہ دل سے مسلمان ہو گیا ہو.مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کا یہ معیار رکھا
ہو کہ اگر میں لڑائی میں غالب آ گیا تو معلوم ہوگا کہ ہمارے بت جن کے لئے لڑ رہا ہوں سچے ہیں لیکن اگر
میں مغلوب ہو گیا تو ثابت ہوگا کہ خدا ایک ہے.بہر حال اس کا میدان جنگ میں مسلمان ہونا اس بات کا
یقینی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ڈر کر مسلمان ہوتا ہے.پس جب اس بات کا امکان تھا کہ وہ دل سے مسلمان ہوتا
ہے تو اسامہ کو اپناہاتھ روک لینا چاہئے تھا اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوئے اور اسامہ
روایت کرتے ہیں کہ آپ مجھ پر اس قدر ناراض ہوئے کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں اس واقعہ سے پہلے
مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا اور اب اس کے بعد مسلمان ہوتا تا کہ آپ کی یہ نا راضگی میرے حصہ میں نہ آتی ہے
پھر تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر کسی وجہ سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوکسی شخص کے متعلق
یہ علم ہو گیا ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا بلکہ محض ڈریا طمع کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو آپ نے اس کا
اسلام قبول نہیں فرمایا.چنانچہ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ کسی لڑائی میں صحابہ نے ایک ایسے کافرکو
قید کیا جو بنو ثقیف کے حلیفوں میں سے تھا.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدی کے پاس سے گزرے
تو اس نے قید سے رہائی پانے کے خیال سے کہا کہ اے محمد! مجھے کیوں قید میں رکھا جاتا ہے میں تو مسلمان
ہوں.آپ نے فرمایا.اگر تم اس حالت سے پہلے اسلام لاتے تو خدا کے حضور یہ اسلام مقبول ہوتا
ل : مسلم کتاب الایمان
Page 343
۳۲۸
اور تم نجات پا جاتے مگر اب نہیں.اس کے بعد آپ نے اس کے بدلے میں دو مسلمان قیدی بنو ثقیف
سے چھڑ والئے اور اسے کفار کو واپس کر دیا.الغرض تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ نے
کسی شخص کو تلوار سے ڈرا کر مسلمان بنایا ہو بلکہ جو مثال ملتی ہے اس کے خلاف ملتی ہے اور یہ اس بات کا
ایک عملی ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی یہ لڑائیاں لوگوں کو جبر مسلمان بنانے کی غرض سے نہ تھیں.اس جگہ اگر کسی کو یہ شبہ پیدا ہو کہ لڑائی میں کسی کافر کی طرف سے اسلام کے اظہار پر اسے چھوڑ دینا یہ
بھی تو ایک رنگ کا جبر ہے تو یہ ایک جہالت کا اعتراض ہوگا.وجہ مخاصمت کے دور ہو جانے پر لڑائی سے ہاتھ
کھینچ لینا حسن اخلاق اور احسان ہے نہ کہ جبر وظلم.کفار عرب کے خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ
کرنا صرف اس بناء پر تھا کہ انہوں نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی تھی اور اسلام کی پُر امن تبلیغ کو بزور روکنا
چاہتے تھے اور اس کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک میں امن اور مذہبی آزادی قائم کرنا
چاہتے تھے.اب اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو قطع نظر اس کے کہ اسے گھر میں بیٹھے ہوئے اسلام
پر شرح صدر پیدا ہوتا ہے یا میدان جنگ میں.جب بھی وہ اسلام کا اظہار کرے گا تو اس کے اس اظہار
کے کم از کم یہ معن ضرور ہوں گے کہ اب اس کی طرف سے وہ خطرہ دور ہو گیا ہے جن کی بناء پر یہ جنگ
ہورہی تھی تو اس صورت میں لازماً اس کے خلاف کارروائی بند کر دی جاوے گی.درحقیقت جیسا کہ ابھی
ظاہر ہو جائے گا جنگ کی ابتداء تو کفار کی طرف سے تھی.پس جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو طبعا اس کے
یہ معنے ہوتے تھے کہ اب وہ جنگ کو ترک کر کے صلح کی طرف مائل ہوتا ہے.پس اس کے خلاف لڑائی روک
دی جاتی تھی.یہی مفہوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اُمِرْتُ
أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " یعنی " مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان کفار سے جنگ
کروں جو اسلام کے خلاف میدان جنگ میں نکلے ہیں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہو جائیں.“ مگر غلطی
سے بعض لوگوں نے اس حدیث کے یہ معنے سمجھ لئے ہیں کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام
کافروں کے خلاف اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائیں.حالانکہ یہ معنے قرآنی تعلیم
اور تاریخی واقعات کے صریح خلاف ہیں اور یہ ایک سراسر خلاف دیانت فعل ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے کسی قول کے وہ معنے چھوڑ کر جو قرآن و تاریخ کے مطابق ہیں اور لغت عرب کی رو سے بھی ان پر کوئی
اعتراض وارد نہیں ہوسکتا وہ معنے کئے جاویں جو واضح قرآنی تعلیم اور صریح تاریخی واقعات کے بالکل خلاف
1 : مسلم بحوالہ مشکوۃ باب حكم الاسراً
: مسلم کتاب الایمان
Page 344
۳۲۹
ہیں.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا یہی مطلب ہے کہ جن کفار نے مسلمانوں کے خلاف
تلوار اٹھائی ہے اور ملک میں نقض امن کا موجب ہو رہے ہیں مجھے ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا گیا
ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کی طرف سے یہ خطرہ جاتا رہے تو مجھے لڑائی بند کر دینے کا حکم
ہے.گویا مراد یہ ہے کہ مجھے ان کفار کے خلاف اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے کہ یا تو جنگ کا طبعی نتیجہ ظاہر
ہو جاوے یعنی یہ لوگ جو اسلام کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں مفتوح ہو جائیں اور جنگ کا خاتمہ ہو جاوے
اور یا وہ اسلام کی صداقت کے قائل ہو کر مسلمان ہو جائیں اور ان کی طرف سے امن شکنی کا کوئی اندیشہ نہ
رہے.اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ صرف اسلام کے اظہار پر ہی لڑائی بند نہیں ہوتی تھی بلکہ اگر کوئی قبیلہ
مسلمانوں کے خلاف جنگ ترک کر دیتا تھا اور مسلمانوں کی سیاسی حکومت کو قبول کر لیتا تھا تو خواہ وہ
کفر وشرک پر ہی قائم رہتا تھا اس کے خلاف بھی جنگ کی کارروائی روک دی جاتی تھی.چنانچہ اس کی بہت
سی مثالیں تاریخ میں مذکور ہیں جو اپنے موقع پر بیان ہوں گی.الغرض اسلام کے اظہار پر لڑائی بند کر دینے
کے حکم کا قطعاً کوئی تعلق جبر سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک حسن سیاست کا فعل ہے جو ہر عقل مند کے نزدیک قابل
تعریف سمجھا جانا چاہئے.یہ تشریح جو اس حدیث کی کی گئی ہے یہ محض عقلی تشریح نہیں بلکہ خود قرآن کریم
کمال صراحت کے ساتھ اس تعلیم کو پیش کرتا ہے کہ اگر کفار اپنے مظالم سے باز آجائیں اور ملک میں فساد
اور امن شکنی کا موجب نہ بنیں تو اس صورت میں مسلمانوں کو ان کے خلاف فوراً کارروائی روک دینی
چاہئے.چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے:
وقتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ
یعنی اے مسلمانو! تم جنگ کروان کفار سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں اس وقت تک کہ
ملک میں فتنہ نہ رہے اور ہر شخص اپنے خدا کے لئے (نہ کسی ڈر اور تشدد کی وجہ سے ) جو دین بھی
چاہے رکھ سکے اور اگر یہ کفار اپنے ظلموں سے باز آجا ئیں تو تم بھی رک جاؤ کیونکہ تمہیں ظالموں
کے سوا کسی کے خلاف جنگی کارروائی کرنے کا حق نہیں ہے.“
اس آیت کی تفسیر حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ عَنِ ابْنِ عُمَرَاَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمُ
حَتَّى لا تَكُونُ فِتْنَةٌ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَقَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ا : سورة بقره : ۱۹۴
Page 345
۳۳۰
اِذْكَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلاً فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى كَثُرَ
الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ے یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑ وان کفار سے جو تم سے لڑتے ہیں اس
وقت تک کہ ملک میں
فتنہ نہ رہے اس کے متعلق ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے اس الہی حکم کی تعمیل یوں کی کہ جبکہ
رسول اللہ کے زمانہ میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور جو شخص اسلام لاتا تھا اسے کفار کی طرف سے دین کے
راستے میں دکھ دیا جاتا تھا اور بعض کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بعض کو قید کر دیا جاتا تھا.پس ہم نے جنگ کیا اس
وقت تک کہ مسلمانوں کی تعداد اور طاقت زیادہ ہو گئی اور نومسلموں کے لئے فتنہ نہ رہا.اس واضح اور بین
آیت اور اس واضح اور بین حدیث کے ہوتے ہوئے ذومعنین حدیث سے جبری اشاعت کی تعلیم ثابت
کرنے کی کوشش کرنا ہر گز دیانت داری کا فعل نہیں سمجھا جا سکتا.صحابہ کی زندگیاں جبر کے خیال کی مکذب ہیں پھر چے ایمان کی بعض علامات ہیں جن سے
وہ پہچانا جاتا ہے اور جو کبھی بھی اس شخص میں.پیدا نہیں ہوسکتیں جو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو.مثلاً سچے ایمان میں محبت ہوتی ہے.اخلاص ہوتا
ہے، قربانی ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے اور ناممکن ہے کہ یہ باتیں اس شخص میں پائی جائیں جس کا ایمان محض
دکھاوے کا ایمان ہے اور جو صرف خوف کی وجہ سے کسی عقیدہ کا اظہار کرتا ہے مگر اس کا دل اس ایمان سے
خالی ہوتا ہے.پس ہمیں صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہئے اور پھر دیکھنا چاہئے کہ کیا ان کا حال ان
لوگوں کا سا نظر آتا ہے جن کا مذہب تلوار کے زور سے تبدیل کیا گیا ہو؟ کیا ان کے ایمان میں محبت کی
بو نہیں ؟ کیا ان کے دل اخلاص سے خالی نظر آتے ہیں؟ کیا ان میں قربانی کی روح نہیں پائی جاتی ؟ کیا ان
میں غیرت کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ اگر یہ نہیں اور ہر گز نہیں.اور یہ سب علامات صحابہ میں موجود ہیں اور نہ
صرف موجود ہیں بلکہ بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں اور ان کی زندگیوں کاہر کارنامہ ان کے ایمان ان کے
اخلاص اور اسلام کے لئے ان کی محبت اور قربانی اور غیرت پر شاہد ہے تو یہ کس قدر ظلم ہو گا کہ ان کے ایمان
کی سچائی پر شبہ کیا جاوے.دور نہ جاؤ عکرمہ بن ابو جہل کی ہی مثال لے لو.باپ ابو جہل ہے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا اور اسی کوشش میں ہلاک ہوا.خود عکرمہ کا یہ حال تھا کہ ہرلڑائی میں وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑا اور اسلام کو مٹانے کے لئے اس نے اپنی تمام کوشش صرف کر دی
اور بالآخر جب مکہ فتح ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی کو اپنے لئے موجب ذلت سمجھ کر مکہ سے
ل : بخاری کتاب التفسير سورة انفال: ۴۰
Page 346
٣٣١
بھاگ گیا اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے
قتل کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم
دیا تھا لیکن بالآخر جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے ایمان واخلاص کا یہ حال تھا کہ حضرت ابوبکر کے
زمانہ خلافت میں اس نے باغیوں کے قلع قمع کرنے میں بے نظیر جان نثاریاں دکھلائیں اور جب ایک
جنگ میں سخت گھمسان کا رن پڑا اور لوگ اس طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے جیسے درانتی کے سامنے گھاس
گرتا ہے اس وقت عکرمہ چند ساتھیوں کو لے کر عین قلب لشکر میں جا کو دا.بعض لوگوں نے منع کیا کہ اس
وقت لڑائی کی حالت سخت خطر ناک ہو رہی ہے اس طرح دشمن کی فوج میں گھسنا ٹھیک نہیں ہے لیکن عکرمہ نہ
مانا اور یہی کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا کہ ” میں لات و عزیٰ کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا
ہوں.آج خدا کے رستے میں لڑتے ہوئے پیچھے نہیں رہوں گا.لڑائی کے خاتمہ پر دیکھا گیا تو اس کی لاش
نیزوں ، تلوار کے زخموں سے چھلنی تھی.مالی قربانی کا یہ حال تھا کہ جب غنائم میں سے عکرمہ کو کوئی حصہ ملتا
تو وہ اسے صدقہ و خیرات اور خدمت دین میں بے دریغ خرچ کر دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ
میں خدا کے دین کے خلاف خرچ کیا کرتا تھا اب جب تک خدا کی راہ میں خرچ نہ کر لوں مجھے چین نہیں
آتا ہے کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے تھے؟
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی ایک اور ثبوت اس بات
کا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ لڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی غرض سے نہ تھیں
خواہش جبر کے خیال کو جھٹلاتی ہے یہ ہے کہ آپ صلح کے خواہش مند رہتے تھے.اور آپ کی
یہ انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح یہ لڑائیاں بند ہو جاویں اور ملک میں امن وامان کی صورت پیدا
ہو.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے سخت سے سخت شرطیں پیش کیں.حتی کہ
اکثر مسلمانوں نے ان شرطوں کے قبول کرنے کو اپنے لئے موجب ذلت سمجھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے کسی بات کی پروا نہ کی اور جس طرح قریش نے کہا اسی طرح ان کی شرطیں مان کر صلح کر لی.اب غور
کا مقام ہے کہ اگر ان لڑائیوں میں آپ کی غرض یہ تھی کہ کفار کو تلوار کے زور سے مسلمان بنایا جاوے
تو صورت حال یہ ہونی چاہئے تھی کہ قریش صلح پر زور دیتے اور ایسی نرم شرطیں پیش کرتے جنہیں مسلمان بخوشی
مان لینے کو تیار ہو جاتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلہ میں سختی کا پہلو اختیار کرتے اور صلح کی
تجویز کو آنوں بانوں سے ٹال کر جنگ چھیڑے رکھتے تا کہ کفار کے جبر مسلمان بنانے کا موقع میسر
ل : اصابه واسدالغابہ واستيعاب
Page 347
۳۳۲
رہتا لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے جو اس بات کا ایک یقینی ثبوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ جس طرح بھی ہو یہ جنگ رک جاوے اور ملک میں امن وامان کی صورت
پیدا ہو.پھر اسی موقع پر جو قرآنی آیت نازل ہوئی وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان لڑائیوں میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض جبری تبلیغ نہ تھی بلکہ قیام امن تھی.چنانچہ بخاری میں روایت آتی ہے
کہ یہ آیت قرآنی که اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا یا یعنی ہم نے تجھے یہ ایک بڑی کھلی کھلی فتح عطا کی
ہے.صلح حدیبیہ ہی کے موقع پر نازل ہوئی تھی.گویا اللہ تعالیٰ نے صلح اور قیام امن کا نام مسلمانوں کے لئے
ایک کھلی کھلی فتح رکھا ہے اور حق بھی یہ ہے کہ صلح حدیبیہ ایک نہایت عظیم الشان فتح تھی جس کے مقابل میں
ایک طرح سے بدر و خندق بھی حقیقت نہیں رکھتے.کیونکہ گوبدر و خندق میں کفار کو ہر سمت ہوئی اور وہ
مسلمانوں کے مقابلہ میں پسپا ہو کر لوٹے لیکن ان جنگوں میں مسلمانوں کو ان کے جہاد کا مقصد حاصل
نہیں ہوا کیونکہ کفارا بھی تک اسی طرح برسر پیکار تھے اور جنگ جاری تھی لیکن حدیبیہ میں گوگوئی کشت و خون
نہیں ہوا اور بظاہر مسلمانوں کو دب کر صلح کرنی پڑی لیکن ان کے جہاد کا مقصد حاصل ہو گیا یعنی جنگ
رک گئی اور ملک میں امن قائم ہو گیا.پس حقیقی فتح صلح حدیبیہ ہی تھی اور اسی لئے خدا نے اس کا نام فتح مبین
رکھا اور یہ ایک نہایت زبر دست ثبوت اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کی لڑائیاں دفاع یا قیام امن کے لئے
تھیں نہ کہ اسلام کو بزور پھیلانے کی غرض سے.صلح کے زمانہ میں مسلمانوں کو غیر معمولی ترقی نصیب ہوئی ایک اور جہت سے بھی اس
سوال پر غور ہوسکتا ہے اور وہ
یہ ہے کہ یہ دیکھا جاوے کہ آیا صلح کے زمانہ میں اسلام کو زیادہ ترقی حاصل ہوئی یا کہ جنگ کے زمانہ
میں.اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ صلح کے زمانہ میں اسلام نے جنگ کے زمانہ کی نسبت غیر معمولی سرعت کے
ساتھ ترقی کی تھی تو یہ اس بات کا ایک عملی ثبوت ہوگا کہ یہ ڈائیاں اسلام کی جبری اشاعت کی غرض سے نہ
تھیں.تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال سے عملی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور صلح حدیبیہ
ہجرت کے چھٹے سال میں وقوع میں آئی.گویا صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں پر قریباً پانچ سال جنگ کی
حالت میں گزرے تھے.ان پانچ سالوں میں مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ ان سپاہیوں کی تعداد سے لگایا
جاسکتا ہے جو اسلامی فوج میں شامل ہو کر شریک جنگ ہوتے تھے.اعلان جنگ ماہ صفر ۲ ہجری میں ہوا اور
: بخاری کتاب التفسیر
: سورة فتح : ۲
Page 348
۳۳۳
قریش کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی لڑائی رمضان ۲ ہجری میں بدر کے موقع پر ہوئی جہاں مسلمان کچھ اوپر تین
سو تھے.دوسری لڑائی شوال ۳ ہجری میں احد کے موقع پر ہوئی جہاں مسلمانوں کی تعداد سات سو تھی.تیسری
لڑائی شوال ۵ ہجری میں ہوئی جو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے اس میں مسلمانوں کی
تعداد تین ہزار تھی.مگر یہ یا درکھنا چاہئے کہ یہ لڑائی چونکہ مدینہ میں ہوئی تھی اس لئے اس میں مسلمان زیادہ
کثرت کے ساتھ شامل ہو سکے تھے وَإِلَّا اگر دور کا سفر ہوتا تو غالبا اس زمانہ میں اس کثرت کے ساتھ
مسلمان شامل نہ ہو سکتے کیونکہ کمزور اور ضعیف اور غریب لوگ کثرت سے رہ جاتے.بہر حال اس جنگ
میں تین ہزار مسلمان شریک ہوئے.اس کے بعد ذ و قعدہ ۶ ہجری میں غزوہ صلح حدیبیہ وقوع میں آیا اور اس
میں ڈیڑھ ہزار مسلمان شامل ہوئے.گویا اس چار پانچ سالہ جنگی زمانہ کے آخری غزوہ میں مسلمانوں کی
تعداد تین سو سے لے کر ڈیڑھ ہزار تک پہنچی تھی اور اگر غزوہ خندق کی تعداد پر بنیادرکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ
تعداد تین ہزار تک پہنچی تھی.اس کے بعد صلح کا زمانہ شروع ہوا اور قریباً پونے دو سال تک صلح رہی لیکن اس
صلح کے زمانہ میں جس غیر معمولی سرعت سے اسلام کی ترقی ہوئی وہ اس تعداد سے معلوم کی جاسکتی ہے
جو غزوہ فتح مکہ کے موقع پر جو رمضان ۸ ہجری میں ہوا مسلمانوں کی تھی.مؤرخین کا اتفاق ہے کہ اس غزوہ
میں اسلامی لشکر کی تعداد دس ہزار نفوس پر مشتمل تھی.گویا چار پانچ سالہ جنگ کے زمانہ میں قابل جہاد
مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ ہزار یا زیادہ سے زیادہ تین ہزار تک پہنچی تھی اور پونے دو سالہ امن کے زمانہ میں
یہ تعداد دس ہزار کو پہنچ گئی اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لڑائیاں اسلام کی جبری اشاعت کی غرض سے نہ
تھیں بلکہ دراصل یہ جنگ اسلام کی ترقی میں ایک روک تھی کیونکہ جو نہی یہ جنگ ختم ہوئی اسلام سرعت کے
ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا.دراصل جنگ کی حالت میں کئی لوگ اسلام کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے اور کئی
کمزور طبیعت لوگ کفار کی مخالفت سے بھی ڈرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے
اصل تبلیغ کا موقع بہت کم ملتا تھا، لیکن جب جنگ رک گئی تو ایک طرف لوگوں کو اسلام کے متعلق غور کرنے کا
موقع مل گیا اور کمز ور طبائع کا خوف جاتا رہا اور دوسری طرف تبلیغ کی سرگرمی زیادہ ہوگئی اور اس کا نتیجہ جو کچھ
ہوا وہ ہمارے سامنے ہے.ایک اور دلیل اس بات کی کہ
تح مکہ کے موقع پر سینکڑوں کار اسلام سے منکر ہے ان حضرت صلی الہ علیہ وسلمکی ہے
لڑائیاں اسلام کی جبری اشاعت کے لئے نہیں تھیں یہ ہے کہ غزوہ مکہ کے موقع پر جب مکہ مسلمانوں کے
Page 349
۳۳۴
ہاتھ فتح ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے
اس وقت گو بعض لوگ قریش مکہ میں سے اپنی مرضی سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن بہت سے قریش کفر پر قائم
رہے اور ان سے قطعاً کوئی تعرض نہیں کیا گیا.اور پھر آہستہ آہستہ جوں جوں ان لوگوں کو اسلام کے متعلق
شرح صدر ہوتا گیا اور وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوتے گئے ایسے لوگوں کی تعداد سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں
تھی.چنانچہ صفوان بن امیہ جو کہ ملکہ کے رئیس امیہ بن خلف کا لڑکا تھا اور اسلام کا سخت دشمن تھاوہ بھی فتح مکہ
کے موقع پر مسلمان نہیں ہوا اور کفر کی حالت میں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر غزوہ حنین میں
شریک ہوا جس میں اور بھی بہت سے مشرک شریک ہوئے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے حسنِ اخلاق سے اس پر اسلام کی حقانیت کھلتی گئی اور بالآخر وہ خود بشرح صدر مسلمان ہو گیا.اب سوال یہ ہے کہ اگر آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ لوگوں کو جبراً مسلمان بناتے تھے تو
فتح مکہ کے بعد جبکہ قریش کی طاقت بالکل ٹوٹ چکی تھی اور اسلامی لشکر مکہ پر قابض تھا اس وقت مکہ والوں کو
کیوں نہ جبراً اسلام میں داخل کیا گیا.فتح مکہ سے بہتر مسلمانوں کے لئے اسلام کی جبری اشاعت کا کون سا
موقع ہوسکتا تھا جبکہ تلوار کے ذرا سے اشارے سے ایک بہت بڑی جماعت اسلام میں داخل کی جاسکتی
تھی لیکن چونکہ اسلام مذہبی آزادی کا پیغام لے کر آیا تھا اور حکم تھا کہ دین کے معاملہ میں قطعا کوئی جبر نہیں
ہونا چاہئے.اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے کمال دیانت داری کے ساتھ
ہر ایک شخص کو اس کے ضمیر پر آزاد چھوڑ دیا کہ جس مذہب پر کوئی چاہے رہے.لیکن اسلام کوئی ایسا مذہب
نہیں تھا کہ مشرکین عرب اس کے متعلق ٹھنڈے طور پر غور کرنے کا موقع پاتے اور پھر اپنے مذہب کے
مقابلہ میں اس کی خوبیوں کے قائل نہ ہوتے.چنانچہ لوہے کی تلوار نے نہیں بلکہ براہین وآیات کی تلوار نے
اپنا کام کیا اور ایک نہایت قلیل عرصہ میں مکہ کی سرزمین شرک کے عصر سے پاک تھی.وجوہات جنگ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کن حالات میں اور کن لوگوں کے خلاف جہاد
بالسیف کی اجازت دی گئی اور اس کی کیا وجوہات تھیں اس سوال کے جواب میں ہمیں
اپنے پاس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کے واقعات واضح ہیں اور ایک ادنی عقل کا آدمی بھی
ان کے مطالعہ سے صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے بشرطیکہ اس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہ ہو.سب سے پہلی بات
تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو جو مظالم قریش نے مسلمانوں پر کئے اور جوجو
: اصابه اسدالغابہ واستيعاب
Page 350
۳۳۵
تدا بیر اسلام کو مٹانے کی انہوں نے اختیار کیں وہ ہر زمانہ میں ہر قسم کے حالات کے ماتحت کسی دوقوموں
میں جنگ چھڑ جانے کا کافی باعث ہیں.تاریخ سے ثابت ہے کہ سخت تحقیر آمیز استہزا اور نہایت دل آزار
طعن و تشنیع کے علاوہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو خدائے واحد کی عبادت اور توحید کے اعلان سے جبر اروکا.ان کو نہایت بے دردانہ طور پر مارا اور پیٹا.ان کے اموال کو نا جائز طور پر غصب کیا.ان کا بائیکاٹ کر کے
ان کو ہلاک و بر باد کرنے کی کوشش کی.ان میں سے بعض کو ظالمانہ طور پر قتل کیا.ان کی عورتوں کی بے حرمتی
کی حتی کہ ان مظالم سے تنگ آکر بہت سے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے لیکن قریش
نے اس پر بھی صبر نہ کیا اور نجاشی کے دربار میں اپنا ایک وفد بھیج کر یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ مہاجرین پھر
مکہ میں واپس آجائیں اور قریش انہیں اسلام سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو جا ئیں اور یا ان کا خاتمہ
کر دیا جاوے.پھر مسلمانوں کے آقا اور سردار کو جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے سخت
تکالیف پہنچائی گئیں اور ہر قسم کے دکھوں میں مبتلا کیا گیا اور قریش کے بھائی بندوں نے طائف میں خدا کا
نام لینے پر آپ پر پتھر برسادیئے حتی کہ آپ کا بدن خون سے تر بتر ہو گیا اور بالآخر مکہ کی قومی پارلیمنٹ میں
سارے قبائل قریش کے نمائندوں کے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمد رسول
اللہ کوقتل کر دیا جاوے تا کہ
اسلام کا نام ونشان مٹ جاوے اور توحید کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو اور پھر اس خونی قرارداد کو عملی جامہ
پہنانے کے لئے نو جوانانِ مکہ جو مختلف قبائل قریش سے تعلق رکھتے تھے رات کے وقت ایک جتھہ بنا کر آپ
کے مکان پر حملہ آور ہوئے لیکن خدا نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ ان کی آنکھوں پر خاک ڈالتے
ہوئے اپنے مکان سے نکل آئے اور غار ثور میں پناہ لی.کیا یہ مظالم اور یہ خونی قرار داد میں قریش کی طرف
سے اعلان جنگ کا حکم نہیں رکھتیں ؟ کیا ان مناظر کے ہوتے ہوئے کوئی عقل مند یہ خیال کر سکتا ہے کہ قریش
مکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہ تھے ؟ پھر کیا قریش کے یہ مظالم مسلمانوں کی طرف سے
دفاعی جنگ کی کافی بنیاد نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا دنیا میں کوئی با غیرت قوم جو خود کشی کا ارادہ نہ کر چکی ہو
ان حالات کے ہوتے ہوئے اس قسم کے الٹی میٹم کے قبول کرنے سے پیچھے رہ سکتی ہے جو قریش نے
مسلمانوں کو دیا ؟ یقینا یقیناً اگر مسلمانوں کی جگہ کوئی اور قوم ہوتی تو وہ اس سے بہت پہلے قریش کے
خلاف میدان جنگ میں اتر آتی مگر مسلمانوں کو ان کے آقا کی طرف سے صبر اور عفو کا حکم تھا.چنانچہ لکھا
ہے کہ جب مکہ میں قریش کے مظالم بہت بڑھ گئے تو عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کے مقابلہ کی اجازت چاہی مگر آپ نے فرمایا انسٹی
Page 351
۳۳۶
أُمِرْتُ بِالْعَفْوِفَلا تُقَاتِلُوا.یعنی ” مجھے ابھی تک عفو کا حکم ہے اس لئے میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں
دے سکتا.چنانچہ صحابہ نے دین کی راہ میں ہر قسم کی تکلیف اور ذلت برداشت کی مگر صبر کے دامن کو نہ چھوڑا
حتی کہ قریش کے مظالم کا پیالہ لبریز ہو کر چھلکنے لگ گیا اور خدا وند عالم کی نظر میں اتمام حجت کی میعاد پوری
ہوگئی.تب خدا نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ تو اس بستی سے نکل جا کہ اب معاملہ عفو کی حد سے گزر چکا ہے
اور وقت آگیا ہے کہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچے.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت قریش کے الٹی میٹم
کے قبول کئے جانے کی علامت تھی اور اس میں خدا کی طرف سے اعلان جنگ کا ایک مخفی اشارہ تھا جسے
مسلمان اور کفار دونوں سمجھتے تھے چنانچہ دارالندوہ کے مشورہ کے وقت جب کسی شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جاوے تو رؤساء قریش نے اس تجویز کواسی بناء پر رد کر دیا تھا
کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ سے نکل گیا تو پھر ضرور مسلمان ہمارے الٹی میٹم کو قبول کر کے ہمارے
خلاف میدان میں نکل آئیں گے اور مدینہ کے انصار کے سامنے بھی جب بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سوال آیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس کے یہ معنے ہیں کہ ہمیں تمام
عرب کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہو جانا چاہئے اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے
اور آپ نے مکہ کے درودیوار پر حسرت بھری نگاہیں ڈال کر فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے ساری بستیوں سے زیادہ
عزیز تھا مگر تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے تو اس پر حضرت ابوبکر نے بھی یہی کہا کہ انہوں
نے خدا کے رسول کو اس کے وطن سے نکالا ہے اب یہ لوگ ضرور ہلاک ہوں گے.خلاصہ کلام یہ کہ جب
تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم رہے آپ نے ہر قسم کے مظالم برداشت کئے لیکن قریش کے
خلاف تلوار نہیں اٹھائی.کیونکہ اول تو پیشتر اس کے کہ قریش کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی سنت اللہ کے
مطابق ان پر اتمام حجت ضروری تھا اور اس کے لئے مہلت درکار تھی.دوسرے خدا کا یہ بھی منشاء تھا کہ
مسلمان اس آخری حد تک عفوا اور صبر کا نمونہ دکھلائیں کہ جس کے بعد خاموش رہنا خود کشی کے ہم معنے
ہو جاوے جو کسی عقل مند کے نزدیک مستحن فعل نہیں سمجھا جا سکتا.تیسرے مکہ میں قریش کی ایک قسم کی
جمہوری حکومت قائم تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شہریوں میں سے ایک شہری تھے.پس حسن
سیاست کا تقاضا تھا کہ جب تک آپ مکہ میں رہیں آپ اس حکومت کا احترام فرمائیں اور خود کوئی امن
شکن بات نہ ہونے دیں اور جب معاملہ عفو کی حد سے گزر جاوے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں.۱ ، ۲ : نسائی کتاب الجہاد
Page 352
۳۳۷
چوتھے یہ بھی ضروری تھا کہ جب تک خدا کی نظر میں آپ کی قوم اپنی کارروائیوں کی وجہ سے عذاب کی
مستحق نہ ہو جاوے اور ان کو ہلاک کرنے کا وقت نہ آجاوے آپ ان میں مقیم رہیں اور جب وہ وقت
آجاوے تو آپ وہاں سے ہجرت فرما جائیں.کیونکہ سنت اللہ کے مطابق نبی جب تک اپنی قوم میں موجود
ہوان پر ہلاک کر دینے والا عذاب نہیں آتا یے اور جب ہلاکت کا عذاب آنے والا ہوتو نبی کو وہاں سے
چلے جانے کا حکم ہوتا ہے.ان وجوہات سے آپ کی ہجرت اپنے اندر خاص اشارات
رکھتی تھی مگر افسوس
کہ ظالم قوم نے نہ پہنچانا اور ظلم و تعدی میں بڑھتی گئی ورنہ اگر اب بھی قریش باز آجاتے اور دین کے
معاملہ میں جبر سے کام لینا چھوڑ دیتے اور مسلمانوں کو امن کی زندگی بسر کرنے دیتے تو خدا ارحم الراحمین
ہے اور اس کا رسول بھی رحمتہ للعالمین تھا یقیناً اب بھی انہیں معاف کر دیا جاتا اور عرب کو وہ کشت وخون
کے نظارے نہ دیکھنے پڑتے جو اس نے دیکھے، مگر تقدیر کے نوشتے پورے ہونے تھے.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی ہجرت نے قریش کی عداوت کی آگ پر تیل کا کام دیا اور وہ آگے سے بھی زیادہ جوش و خروش
کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے.ان غریب اور کمزور مسلمانوں پر ظلم وستم ڈھانے کے علاوہ جو ابھی تک مکہ میں ہی تھے سب سے پہلا
کام جو قریش نے کیا وہ یہ تھا کہ جو نہی کہ ان کو یہ علم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بچ کر نکل گئے
ہیں وہ آپ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور وادی بلکہ کی چپہ چپہ زمین آپ کی تلاش میں چھان
ماری اور خاص غار ثور کے منہ تک بھی جا پہنچےمگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی اور قریش کی آنکھوں پر
ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ عین منزل مقصود تک پہنچ کر خائب و خاسر واپس لوٹ گئے.جب وہ اس تلاش میں
مایوس ہوئے تو انہوں نے عام اعلان کیا کہ جو شخص بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا
اسے ایک سو اونٹ جو آج کل کی قیمت کے حساب سے قریباً بیس ہزار روپیہ بنتا ہے انعام دیا جائے
گا اور اس انعام کے لالچ میں مختلف قبائل کے بیسیوں نوجوان آپ کی تلاش میں چاروں طرف نکل
کھڑے ہوئے.چنانچہ سراقہ بن مالک کا تعاقب جس کا ذکر کتاب کے حصہ اوّل میں گزر چکا ہے اسی
انعامی علان کا نتیجہ تھا مگر اس تدبیر میں بھی قریش کو نا کامی کا منہ دیکھنا پڑا.غور کیا جاوے تو دو قوموں میں
جنگ چھڑ جانے کے لئے صرف یہی ایک وجہ کافی ہے کہ کسی قوم کے آقا وسردار کے متعلق دوسری قوم اس
طرح انعام مقرر کرے.بہر حال یہ تجویز بھی کارگر نہ ہوئی اور قریش کو علم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ا : سورۃ انفال : ۳۴
Page 353
۳۳۸
امن و عافیت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے ہیں تو جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے رؤسائے قریش نے مدینہ کے
رئیس اعظم عبد اللہ بن اُبی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کے نام ایک خطرناک تہدیدی خط ارسال کیا
جس میں لکھا کہ :
إِنَّكُمْ اَوَيْتُمُ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نَقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ اَوْ تُخْرِجُنَّهُ أَوْلَنَسِيْرَنَّ إِلَيْكُمُ بِأَجْمَعِنَا حَ
نَقْتُلَ مَقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَ كُمْ
یعنی تم لوگوں نے ہمارے آدمی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو پناہ دی ہے اور ہمیں خدا کی قسم
ہے کہ یا تو تم اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے خلاف جنگ کرو یا کم سے کم اسے اپنے شہر سے نکال
دوور نہ ہم ضرور بالضرور اپنا سارا لا ولشکر لے کر تم پر حملہ آور ہو جائیں گے اور تمہارے مردوں
کو قتل کر ڈالیں گے اور تمہاری عورتوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے لئے جائز کر لیں گے.اس خط سے جو تشویش بے چارے مہاجرین کو دامن گیر ہو سکتی تھی وہ تو ظاہر ہی ہے لیکن انصار میں بھی
اس نے ایک خطر ناک سنسنی پیدا کر دی.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ خود عبد اللہ
بن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور اسے یہ سمجھا کر ٹھنڈا کیا کہ تمہارے اپنے عزیز واقارب میرے ساتھ
ہیں کیا تم اپنے جگر گوشوں سے جنگ کرو گے؟ انہی ایام کے قریب سعد بن معاذ رئیس اوس عمرہ کی غرض سے
مکہ آئے تو انہیں دیکھ کر ابوجہل کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے بگڑ کر کہا کہ تم نے (نعوذ باللہ ) اس
مرتد محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کو پناہ دی ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ تم اس کی حفاظت کر سکو گے.اس زمانہ
میں قریش کو اسلام کے استیصال کا اتنا خیال تھا کہ ولید بن مغیرہ رئیس مکہ جب مرنے لگا تو بے اختیار ہوکر
رونے لگ گیا.لوگوں نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے.اس نے جواب دیا.میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد محمد
(صلی اللہ علیہ وسلم ) کا دین نہ پھیل جاوے.رؤساء قریش نے کہا تم فکرمند نہ ہو.” ہم اس بات کے
ضامن ہیں کہ اس کے دین کو نہیں پھیلنے دیں گے.“ یہ سب ہجرت کے بعد کی باتیں ہیں جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مظالم سے تنگ آکر مکہ کو چھوڑ چکے تھے اور خیال کیا جاسکتا تھا کہ اب قریش
مسلمانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے.پھر اسی پر بس نہیں بلکہ جب قریش نے دیکھا کہ اوس وخزرج
مسلمانوں کی پناہ سے دستبردار نہیں ہوتے اور اندیشہ ہے کہ اسلام مدینہ میں جڑ نہ پکڑ جاوے تو انہوں نے
دوسرے قبائل عرب کا دورہ کر کر کے ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور چونکہ بوجہ خانہ کعبہ
ل : ابوداؤد کتاب الخراج
بخاری
: تاریخ الخمیس
Page 354
۳۳۹
کے متولی ہونے کے قریش کا سارے قبائل عرب پر ایک خاص اثر تھا اس لئے قریش کی انگیخت سے کئی قبائل
مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے اور مدینہ کا یہ حال ہوگیا کہ گویا اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ
ہے.چنانچہ یہ روایت او پر گزرچکی ہے کہ:
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ الْمَدِينَةَ وَاوَتْهُمُ الْأَنْصَارُ رَمَتْهُمُ
العَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ فَكَانُوا لَا يَبِيتُونَ إِلَّا بِالسّلاح وَلَا يَصْبَحُونَ إِلَّا فِيْهِ وَقَالُوا أَتَرَوْنَ
أَنَّا نَعِيْشُ حَتَّى نَبِيِّتُ امِنِينَ لَانَخَافُ إِلَّا اللَّهَ
یعنی ابی بن کعب جو کبار صحابہ میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ میں تشریف لائے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب
ایک جان ہو کر ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا.چنانچہ ان دنوں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ خوف کی
وجہ سے وہ راتوں کو بھی ہتھیار لگا لگا کر سوتے تھے اور دن کو بھی ہتھیار لگائے پھرتے تھے کہ کہیں
کوئی اچانک حملہ نہ ہو جاوے اور وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھئے ہم اس وقت تک
بچتے بھی ہیں یا نہیں کہ ہمیں امن کی راتیں گزارنے کا موقع ملے گا اور خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ
رہے گا.“
خودسرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ
مَاقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَسْهَرُ مِنَ اللَّيْلِ ” جب شروع شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں
تشریف لائے تو دشمن کے حملہ کے خوف سے آپ عمو ماراتوں کو جاگا کرتے تھے.“
اسی زمانے کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے:
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أنْ يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ
فَاوِيكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ EO
مسلمانو! وہ زمانہ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور ملک میں بہت کمز ور سمجھے جاتے تھے اور
تمہیں یہ خوف لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر تباہ کر دیں.پھر خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی
نصرت سے تمہاری تائید فرمائی اور تمہارے لئے پاکیزہ رزق کے دروازے کھولے.پس تمہیں
شکر گزار ہوکر رہنا چاہئے.“
ہے : حاکم وطبرانی بحوالہ لباب النقول
نائی
۳ : سورۃ انفال : ۲۷
Page 355
۳۴۰
یہ بیرونی خطرات کا حال تھا اور خود مدینہ کے اندر یہ حالت تھی کہ ابھی تک ایک معتد بہ حصہ اوس وخزرج
کا شرک پر قائم تھا اور گو وہ بظاہر اپنے بھائی بندوں کے ساتھ تھے لیکن ان حالات میں ایک مشرک کا کیا
اعتماد کیا جاسکتا تھا.پھر دوسرے نمبر پر منافقین تھے جو بظاہر اسلام لے آئے تھے مگر در پردہ وہ اسلام کے
دشمن تھے اور مدینہ کے اندر ان کا وجود خطر ناک احتمالات پیدا کرتا تھا.تیسرے درجہ پر یہود تھے جن کے
ساتھ گوا ایک معاہدہ ہو چکا تھا مگر ان یہود کے نزدیک معاہدہ کی کوئی قیمت نہ تھی.غرض اس طرح خود مدینہ
کے اندر ایسا مواد موجود تھا جو مسلمانوں کے خلاف ایک مخفی ذخیرہ بارود سے کم نہ تھا اور قبائل عرب کی ذراسی
چنگاری اس بارود کو آگ لگانے اور مسلمانان مدینہ کو بھک سے اڑا دینے کے لئے کافی تھی.اس نازک
وقت میں جس سے زیادہ نازک وقت اسلام پر
کبھی نہیں آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وحی نازل
ہوئی کہ اب تمہیں بھی ان کفار کے مقابلہ میں تلوار استعمال کرنی چاہئے جو تمہارے خلاف تلوار لے کر
سراسر ظلم و تعدی سے میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور جہاد بالسیف کا اعلان ہو گیا.اس وقت لڑائی کے قابل مسلمانوں کی تعداد چند سو سے زیادہ نہیں تھی اور ان چند سونفوس میں بھی
کثرت ان لوگوں کی تھی جو سخت درجہ کمزوری اور غربت کی حالت میں تھے اور بعض کو تو آئے دن فاقے کی
نوبت رہتی تھی اور ان میں سے بہت کم ایسے تھے جو اپنے لئے لڑائی کا معمولی سامان تک مہیا کر سکتے
تھے.دوسری طرف فریق مقابل کا یہ حال تھا کہ مذہبی لحاظ سے تو بلا استثناء سارا ملک دشمن تھا.عملاً بھی
قریش کے علاوہ جن کی تعداد ہزار ہا نفوس پر مشتمل تھی اور جو دولت وثروت اور سامان حرب میں مسلمانوں
سے کئی درجہ زیادہ مضبوط تھے بہت سے دوسرے قبائل عرب قریش کے پشت پناہ بن گئے تھے اور ان
خطرات کی وجہ سے مسلمانوں کو راتوں
کو نیند نہیں آتی تھی.ایسی نازک حالت میں خدا کا یہ حکم نازل ہوا کہ
اے مسلمانو! اب تم بھی ان کفار کے مقابلہ میں تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہو.اس جہاد کی غرض وغایت کے
متعلق کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتا کیونکہ ایسی حالت میں صرف وہی شخص میدان میں نکل سکتا ہے
جود و باتوں میں سے ایک کا ارادہ کر چکا ہو یا یہ کہ اب میں نے مرنا تو ہے ہی کیوں نہ مردوں کی طرح
میدان میں جان دوں اور یا یہ کہ اب مرنے سے بچنے کا اگر کوئی امکانی ذریعہ ہو سکتا ہے تو صرف یہ کہ تلوار
لے کر میدان میں نکل جاؤں اور پھر ہر چہ باداباد.مسلمانوں کی ابتدائی لڑائیاں اسی آخر الذکر عزم کے
ماتحت تھیں مگر باوجود اس خدائی حکم اور مسلمانوں کے اس اضطراری عزم کے اس وقت بہت سے کمزور دل
مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ لڑائی کے خیال سے ان کے دل بیٹھے جاتے تھے.چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے:
Page 356
۳۴۱
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً
وَقَالُوْارَ بَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
یعنی جب مسلمانوں پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ کفار سے اتنا ڈرتا تھا کہ
خدا کے ڈر سے بھی ان کا ڈر بڑھا ہوا تھا اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اے رب ہمارے تو نے ابھی
سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا اور کیوں ہمیں تھوڑی دیر اور مہلت نہ دی.“
پھر فرماتا ہے:
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرُهُ لَكُمْ وَعَلَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُـ
وَعَلَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ O
د یعنی اے مسلمانو! ہم جانتے ہیں کہ جہاد بالسیف تم پر ایسے وقت میں فرض کیا گیا ہے کہ
وہ تمہارے لئے ایک مشکل اور تکلیف دہ کام ہے مگر یا درکھو ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو اپنے لئے
موجب تکلیف سمجھو مگر دراصل وہ اچھی ہو.یا تم ایک چیز کو اپنے لئے اچھا سمجھو مگر دراصل وہ بُری
ہوا اور بیشک اللہ اس بات کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے.“
جہاد کے متعلق پہلی قرآنی آیت مؤرخین لکھتے ہیں کہ جہاد بالسیف کے متعلق سب سے پہلی آیت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ۱۲ صفر ۲ ہجری کے مطابق
۱۵/ اگست ۶۶۲۳ ۴ کو نازل ہوئی جبکہ آپ کو مدینہ میں تشریف لائے قریباً ایک سال کا عرصہ گزرا تھا
اور وہ یہ آیت ہے:
أذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ نُ الَّذِينَ أُخْرِجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوتُ وَ مَسجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ الله مَنْ يَنْصُرُهُ
اِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزُ
اجازت دی جاتی ہے لڑنے کی مسلمانوں کو جن کے خلاف کفار نے تلوار اٹھائی
ہے.کیونکہ وہ ( مسلمان ) مظلوم ہیں اور ضرور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے.وہ ظلم کے
: سورۃ نساء : ۷۸
: توفيقات الهاميه
: سورة بقرة : ۲۱۷
ے : زرقانی
ه: حج : ۴۰ - ۱
Page 357
۳۴۲
ساتھ اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے
اور اگر اللہ تعالیٰ نہ روکے ( دفاعی جنگ کی اجازت دے کر ) ایک قوم کو دوسری قوم کے خلاف
تو یقیناً راہبوں کے صومعے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہود کے معاہد اور مسلمانوں کی مسجدیں
جن میں کثرت کے ساتھ خدا کا نام لیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ہاتھ سے تباہ و برباد کر دی
جاویں اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ
قومی اور غالب خدا ہے.“
اس آیت کے الفاظ جس وضاحت اور صفائی کے ساتھ ابتدائی اسلامی جنگوں کی غرض وغایت اور اس
وقت کے مسلمانوں کی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں وہ کسی تفسیر کی محتاج نہیں ہے اور اگر غور سے دیکھا جاوے
تو اس آیت سے چار باتیں ثابت ہوتی ہیں.اول یہ کہ اس جنگ میں ابتدا کفار کی طرف سے تھی جیسا کہ
يُقَاتَلُونَ “ کے لفظ سے ظاہر ہے.دوسرے یہ کہ کفار مسلمانوں پر سخت ظلم کیا کرتے تھے اور ان کے
یہی مظالم جنگ کا باعث تھے جیسا کہ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا “ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے.تیسرے یہ کہ
کفار کی غرض یہ تھی کہ دین اسلام کو تلوار کے زور سے نیست و نابود کر دیں جیسا کہ لَهُدِّمَتْ “ کے لفظ
میں اشارہ ہے.چوتھے یہ کہ مسلمانوں کے اعلان جنگ کی غرض خود حفاظتی اور دفاع تھی جیسا کہ
لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ “ کے لفظ سے پایا جاتا ہے.الغرض یہ آیت کریمہ جو جہاد بالسیف کے متعلق سب
سے پہلی آیت ہے کمال صفائی کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ ان جنگوں میں ابتداء کفار کی طرف سے تھی جو
اسلام کو بزور مٹانا چاہتے تھے اور مسلمان مظلوم تھے اور انہوں نے محض خود حفاظتی اور دفاع میں تلوار
اٹھائی تھی.میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین اسلام کی طرف سے جہاد بالسیف کے متعلق جتنے بھی اعتراض ہوئے
ہیں ان کے جواب کے لئے یہی ایک آیت کافی ہے اگر کوئی سمجھے.قرآن سب سے زیادہ صحیح تاریخی شہادت ہے اس جگہ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ شبہ
گزرے کہ قرآن تو خود مسلمانوں کی اپنی
مذہبی کتاب ہے اس کی شہادت کو کس طرح یہ رتبہ دیا جا سکتا ہے کہ اس پر ایک اہم تاریخی واقعہ کی بنیا درکھی
جاوے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا شبہ صرف اس شخص کے دل میں پیدا ہوسکتا ہے جوفن تاریخ اور اسلامی
لٹریچر سے قطعاًنا واقف ہو.قرآن کریم کا تو وہ مرتبہ ہے کہ جس کے مقابل میں اسلامی تاریخ کا کوئی دوسرا
ریکارڈ کچھ حقیقت نہیں رکھتا.بھلا حدیث و تاریخ کی روایت کو باوجود محدثین اور مؤرخین کی اتنی چھان بین
Page 358
۳۴۳
کے قرآن کے مقابلہ میں کیا وزن حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ صرف خوش عقیدگی کا دعوی نہیں ہے بلکہ ایک پتین
صداقت ہے جس کو دوست و دشمن نے تسلیم کیا ہے.بات یہ ہے کہ یہاں کسی مذہبی مسئلہ کا سوال نہیں ہے
کہ کوئی غیر مسلم یہ کہ کر قرآن کے خیال کو رد کر دے کہ میں قرآنی تعلیم کو خدا کی طرف سے نہیں مانتا.بلکہ
یہاں تاریخی شہادت کا سوال ہے اور یہ مسلم ہے کہ تاریخی شہادت سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ
مستند وہی ہوتی ہے جو اس وقت کی ہو جبکہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور ان لوگوں کی ہو جن کے سامنے وہ واقع ہوا
ہے اور وہ اسی وقت ضبط تحریر میں آجاوے اور پھر اس کے بعد بھی ہر قسم کی تحریف سے پاک رہے اور اس
جہت سے جو مرتبہ قرآن کریم کو حاصل ہے وہ ہر گز کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے.قرآن کریم آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی نہ صرف ضبط تحریر میں آ گیا تھا بلکہ بہت سے حفاظ نے اس کو اپنے ذہنوں
میں لفظ بلفظ محفوظ بھی کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ آج تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہا ہے اور اب بھی بعینہ
اسی شکل وصورت میں ہے جیسا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں تھا.چونکہ یہ ایک
مسلّمہ حقیقت ہے، میں اس بحث میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چاہتا.ورنہ میں بتاتا کہ قرآن کی صحت
کامرتبہ کیسا عالی شان ہے اور اس کے مقابلہ میں کسی اور سند کولا نا صداقت کی ہتک کرنا ہے.صرف
بطور مثال کے دو شہادتیں پیش کرتا ہوں اور وہ بھی ان لوگوں کی جو مخالفین اسلام میں سے ہیں.وَالْفَضْلُ
مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ.سرولیم میور جو ایک بہت مشہور انگریز مؤرخ گزرے ہیں اور جن کی کتاب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے
سواخ میں غالباً سب مغربی کتب سے زیادہ متداول ہے وہ اپنی کتاب ”لائف آف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )
میں لکھتے ہیں :
اس بات کی مضبوط ترین شہادت موجود ہے کہ مسلمانوں کا قرآن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )
کے وقت سے لے کر آج تک غیر محرف و مبدل رہا ہے.“
پھر لکھتے ہیں :
مسلمانوں کے قرآن کا ہماری انا جیل کے ساتھ مقابلہ کرنا جو بدقسمتی سے بہت کچھ محرف ومبدل
ہوچکی ہیں دو ایسی چیزوں کا مقابلہ کرنا جن کو ایک دوسرے سے کوئی بھی مناسبت نہیں.“
پھر لکھتے ہیں :
اس بات کی پوری پوری اندرونی اور بیرونی ضمانت موجود ہے کہ قرآن اب بھی اسی
Page 359
۳۴۴
صورت وشکل میں ہے جیسا کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے وقت میں تھا.یہ یادرکھنا چاہئے کہ سرولیم میور اسلام کے دوستوں میں سے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنی کتاب میں
جابجا اسلام اور بانی اسلام پر سخت حملے کئے ہیں مگر قرآن کی وہ ارفع شان ہے جسے کسی کا تعصب گردآلود
نہیں کرسکتا.پھر نولڈ یکی جو جر منی کا ایک نہایت مشہور عیسائی مستشرق گزرا ہے اور جو اس فن میں گویا استاد
مانا گیا ہے قرآن کے متعلق لکھتا ہے کہ:
آج کا قرآن بعینہ وہی ہے جو صحابہ کے وقت میں تھا.“
پھر لکھتا ہے کہ:
،،
یوروپین علماء کی یہ کوشش کہ قرآن میں کوئی تحریف ثابت ہو سکے قطعاً نا کام رہی ہے.“
یہ تو قرآن کی عام صحت کے متعلق اہل مغرب کی شہادت ہے.پھر خاص تاریخی نقطہ نگاہ سے سرولیم
میور لکھتے ہیں کہ :
اسلام اور بانی اسلام کے متعلق تاریخی تحقیقات کرنے کے لئے قرآن ایک بنیادی پتھر
ہے جس سے ہر واقعہ کی صحت جانچی جاسکتی ہے“
پھر لکھتے ہیں :
،،
د نبی اسلام کے سوانح کے لئے قرآن ایک یقینی کلید ہے.“
پھر پروفیسر نکلسن جو انگلستان کا ایک مسیحی مستشرق ہے اور جس کی تصنیف ”عرب کی ادبی تاریخ “ بہت
شائع اور متعارف ہے، اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے:
اسلام کی ابتدائی تاریخ کا علم حاصل کرنے کے لئے قرآن ایک بے نظیر اور ہر قسم کے
،،
شک وشبہ سے بالا کتاب ہے اور یقیناً بدھ مذہب اور میسحیت یا کسی قدیم مذہب کو اس قسم کا
مستند تاریخی ریکارڈ حاصل نہیں ہے جیسا کہ قرآن میں اسلام کو حاصل ہے.“
الغرض قرآن کریم ابتدائی اسلامی تاریخ کا بالکل سچا اور سب سے زیادہ مستند ریکارڈ ہے اور اس کو وہ
مرتبہ حاصل ہے جو حدیث یا سیرت یا تاریخ کو حاصل نہیں ہے.پس جب قرآن کریم اپنی اس آیت میں
جو سب سے پہلے جہاد بالسیف کی اجازت میں نازل ہوئی نہایت واضح اور غیر مشکوک الفاظ میں یہ شہادت
: دیکھودیباچہ لائف آف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) مصنفہ سرولیم میور
: انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا
: دیکھو لائف آف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) مصنفہ میور : دیکھو عرب کی ادبی تاریخ مصنفہ نکلسن صفحہ ۱۴۳
Page 360
۳۴۵
دے رہا ہے کہ ابتدا کفار کی طرف سے تھی اور مسلمانوں نے محض دفاع میں تلوار اٹھائی تھی تو رکیک
اور بودے استدلالات کر کے مسلمانوں کی طرف سے ابتدا ہونے کا ثبوت تلاش کرنا ہرگز دیانت داری
کا فعل نہیں سمجھا جاسکتا.جہاد کے متعلق بعض دوسری قرآنی آیات اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی
بعض دوسری آیات بھی درج کردی جاویں جو
وقتاً فوقتاً جہاد بالسیف کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں کیونکہ ان سے ابتدائی اسلامی
جنگوں کے حالات پر ایک ایسی روشنی پڑتی ہے جو کسی دوسری جگہ میسر نہیں آسکتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ اشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُوكُمْ فِيْهِ فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ وَقْتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الَّذِيْنُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوا
فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ
اے مسلمانو !الڑ واللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں مگر دیکھنا زیادتی نہ کرنا
کیونکہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا.اور لڑ وان کفار سے جو تم سے لڑتے ہیں جہاں
بھی ان
کا اور تمہارا سا منا ہو.اور نکالو ان کو اس جگہ سے جہاں سے وہ تمہیں نکالیں.یعنی جہاں
بھی وہ تمہارے اثر کو بزور مٹانا چاہیں تم ان کا مقابلہ کرو.اور بیشک وہ فتنہ جس کے یہ لوگ
مرتکب ہو رہے ہیں وہ قتل سے بھی سخت تر ہے مگر ہاں لڑائی مت کر وحرم کے علاقہ میں لیکن اگر یہ
کفار خود تم سے حرم میں لڑائی کی ابتداء کریں تو پھر بے شک تم بھی ان کا مقابلہ کرو.کیونکہ
ناشکر گزاروں کی یہی سزا ہے اور اگر کفار اس سے باز آجائیں تو جانو کہ اللہ بھی غفور و رحیم ہے
اور اے مسلمانو! تم لڑ وان کفار سے اس وقت تک کہ ملک میں فتنہ نہ رہے اور دین خدا ہی کے
لئے ہو جاوے.یعنی دین کے معاملہ میں سوائے خدا کے اور کسی کا خوف نہ رہے اور ہر شخص آزادی
سے اپنی ضمیر کے مطابق جو دین پسند کرے وہ رکھ سکے اور اگر یہ کفار جنگ سے باز آجائیں تو تم
بھی فور آرک جاؤ.کیونکہ کسی کو جنگ کشی کا حق نہیں ہے مگر صرف ظالموں کے خلاف.“
ا : سورة بقرة: ۱۹۱ تا ۱۹۴
Page 361
۳۴۶
یہ آیت بھی اپنے معانی میں نہایت واضح ہے اور اس سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد
کا حکم صرف ان لوگوں کے خلاف دیا گیا تھا جو ان سے دین کے معاملہ میں جنگ کرتے تھے اور ان کو تلوار
کے زور سے ان کے دین سے پھیرنا چاہتے تھے اور نیز یہ کہ مسلمانوں
کو یہ بھی حکم تھا کہ اگر یہ کفار جنگ سے
باز آجائیں تو تمہیں بھی چاہئے کہ فور آرک جاؤ اور اس آیت میں جنگ کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے اور وہ یہ
کہ ملک میں فتنہ نہ رہے اور مذہبی آزادی قائم ہو جاوے.پھر فرماتا ہے:
وَإِنْ جَنَحُوْ الِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اور اگر یہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو اے نبی تمہیں چاہئے کہ تم بھی صلح کی طرف جھک
جاؤ اور اللہ پر توکل کرو.بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے.“
پھر فرماتا ہے:
وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ
مَامَنَه -
اور اگر کوئی مشرک تمہاری پناہ میں داخل ہو کر تمہارے پاس تحقیق دین کے لئے آنا
چاہے تو اسے آنے دو اور پھر اپنی حفاظت میں اسے اس کی امن کی جگہ میں واپس پہنچادو.“
پھر فرماتا ہے:
وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقَ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيرٌ.اور وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی.یعنی وہ تمہارے
مصائب میں تمہارا ہاتھ نہیں بٹاتے وہ تمہاری سیاسی دوستی کے حقدار نہیں ہیں.البتہ اگر وہ کسی
دینی معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان کو مدد دو لیکن ان کفار کے خلاف
تمہیں مدد دینے کی اجازت نہیں ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، اور اے مومنو! ہوشیار ہو کہ
خدا تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے.“
: سورۃ انفال : ۶۲
: سورۃ توبہ : ۶
: انفال : ۷۳
Page 362
۳۴۷
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
اور پورا کر واپنے عہد کو کیونکہ یقینا تمہیں اپنے عہد کے متعلق خدا کے سامنے جواب دہ
ہونا پڑے گا.“
پھر فرماتا ہے:
لَا يَنْهُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهُنَّكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قُتَلُوكُمْ
في الدِيْنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظُهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ O - :
نہیں منع کرتا اللہ تم کو ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملہ میں لڑائی
نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یہ کہ تم ان سے مہربانی کا سلوک کرو اور
ان سے عدل اور احسان سے پیش آؤ.بیشک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا
ہے.اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تم کو کہ دوست بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے خلاف دین کے
معاملہ میں لڑائی کی اور تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا یا تمہارے نکالے جانے میں اعانت کی.اور جو کوئی دوستی لگائے گا ایسے دشمنوں کے ساتھ تو ایسے لوگ ظالموں میں سے سمجھے جائیں گے.“
پھر فرمایا:
يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى
بلکہ تم
الَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَO
”اے مومنو! چاہئے کہ تم دنیا میں خدا کے لئے عدل وانصاف کو قائم کرو اور چاہئے کہ ہرگز
نہ آمادہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش نہ آؤ
یہ تمہیں چاہئے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل وانصاف کا معاملہ کرو کیونکہ عدل وانصاف کرنا
تقویٰ کا تقاضا ہے.پس تم متقی بنو اور یا درکھ کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے.“
جہاد بالسیف کے متعلق بعض اصولی روایات یہ قرآن شریف کا بیان گزرا ہے اور گو قرآن
کے بیان کے بعد کسی اور بیان کی حاجت نہیں
ل : بنی اسرائیل : ۳۵
: ممتحنه : ۹ ، ۱۰
۳: مائده : ۹
Page 363
۳۴۸
رہتی لیکن اس خیال سے کہ کسی شخص کو یہ شبہ نہ گزرے کہ شاید عام تاریخی روایات قرآن کے مخالف ہوں
اس جگہ بعض روایات بھی درج کر دینی مناسب ہیں جن سے اسلام کی ابتدائی لڑائیوں پر ایک اصولی روشنی
پڑتی ہے.سو روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ:
يأَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّا لِقَاءَ الْعَدُقِ وَاسْتَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا
”اے مسلمانو ! تمہیں چاہئے کہ دشمن کے مقابلہ کی خواہش نہ کیا کرو اور خدا سے امن وعافیت کے خواہاں
رہو اور اگر تمہاری خواہش کے بغیر حالات کی مجبوری سے کسی دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو
پھر ثابت قدمی دکھاؤ.“
اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ کفار کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا تھا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا چیلنج قبول کر لیا تھا اور جنگ کا آغاز ہو چکا تھا پھر بھی مسلمانوں
کو یہی حکم تھا کہ وہ اس جنگ کے جزوی مقابلوں میں بھی لڑائی کی خواہش نہ کیا کریں.ہاں البتہ اگر
دشمن سے مقابلہ ہو جاوے تو پھر جم کر لڑیں.پھر روایت آتی ہے کہ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شُجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً
وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص ہے کہ وہ اپنی بہادری
کے اظہار کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص ہے کہ وہ خاندانی یا قومی غیرت کی وجہ سے لڑتا
ہے اور ایک شخص ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے لڑائی کرتا ہے.ان میں سے کون سا شخص
فی سبیل اللہ لڑنے والا سمجھا جاسکتا ہے.آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں بلکہ خدا کے رستے میں وہ
شخص لڑنے والا سمجھا جائے گا جو اس لئے لڑتا ہے کہ جو کوشش کفار کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے
دین کو مغلوب کرنے کی جاری ہے اس کا قلع قمع ہو اور خدا کا دین کفار کی ان کوششوں کے مقابل
پر غالب آجاوے.“
عَنْ بَرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
ل : بخاری و مسلم وابو داؤد
ہے : بخاری و مسلم وابوداؤد و ترمذی ونسائی
Page 364
۳۴۹
إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلْثِ خِلَالٍ فَإِنْ أَجَابُوكَ
فَاقْبِلُ مِنْهُمْ وَكَفِّ عَنْهُمْ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ فَإِنْ اَجَابُوكَ فَاقْبِلُ مِنْهُمْ وَكَفٌ
هُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَاخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ
فَعَلُوا ذَالِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَبَوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا
فَاخْبِرُهُمُ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِى عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى
الَّذِي يَجُرِى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ وَالْفَيءِ شَيٍّ إِلَّا أَنْ
يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ هُمُ اَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبِلْ
مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ آبَوُا فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَقَاتِلُهُمْ
یعنی بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوجی
دستہ روانہ کرتے تھے تو اس کے امیر کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنے دشمنوں کے
سامنے ہو یعنی اس قوم سے تمہاری مٹھ بھیڑ ہو جاوے جن سے تمہاری لڑائی چھڑی ہوئی ہے تو
لڑائی شروع کرنے سے پہلے انہیں تین باتوں کی دعوت دیا کرو.اگر ان تینوں میں سے وہ کوئی
ایک بھی مان لیں تو پھر ان سے مت لڑو.سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو.اگر وہ مان
لیں تو ان کے اسلام کو قبول کرو اور ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لو.پھر اس کے بعد تم ان کو مدینہ کی
طرف ہجرت کرنے کی تحریک کرو اور ان سے کہو کہ اگر وہ ہجرت کریں گے تو ان کو مہاجرین کے
حقوق دئے جائیں گے اور مہاجرین والی ذمہ داری بھی ان پر ہوگی.اگر وہ ہجرت پر رضا مند نہ
ہوں تو پھر ان سے کہہ دو کہ وہ اسلام میں تو داخل ہو جائیں گے لیکن مہاجرین کے حقوق ان
کو نہیں ملیں گے کیونکہ وہ صرف جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتے ہیں.اور اگر وہ تمہاری
دعوت اسلام کو ہی رد کر دیں تو پھر ان سے کہو کہ ٹیکس دینا قبول کر کے اسلامی حکومت کے ماتحت
آ جاؤ.اگر وہ یہ صورت مان لیں تو پھر بھی ان سے لڑائی مت کرو لیکن اگر وہ انکار کریں تو پھر
خدا کا نام لے کر ان سے لڑو.“
پھر روایت آتی ہے کہ :
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
ل : مسلم وابوداؤ دوترندی
Page 365
۳۵۰
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَرْيَةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَغَارَ اسْتَحْتَقْتُ فَرَسِي فَسَبِقُتُ أَصْحَابِي
فَتَلَقَّانِى أَهْلُ الْحَيِّ بِالرَّنِينَ فَقُلْتُ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالُوْهَا فَلَا مَنِي
أَصْحَابِي فَقَالُوا حَرَّمْتَنَا الْغَنِيْمَةَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَنَ لِى مَا صَنَعْتُ ثُمَّ قَالَ لِي أَمَا إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلّ إِنْسَانِ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجْرِ وَقَالَ أَمَا إِنِّي
سَأَكْتُبُ لَكَ الْوِصَائَةَ بَعْدِي فَفَعَلَ وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ
یعنی حارث بن مسلم بن حارث اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا.جب ہم منزل مقصود پر پہنچے تو میں نے اپنے گھوڑے کو
ایر لگا کر اپنے آپ کو ساتھیوں سے آگے کر لیا.جب قبیلہ کے لوگ مجھے ملے تو وہ اچانک حملہ کی
وجہ سے ڈر کر عاجزی کرنے لگ گئے.جس پر میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان
ہو گئے.اس پر میرے بعض کمزور ساتھیوں نے مجھے ملامت کی کہ تم نے ہمیں غنیمت سے محروم
کر دیا ہے.پھر جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو لوگوں نے اس
واقعہ کی آپ کو اطلاع دی.آپ نے مجھے بلایا اور میرے فعل کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم نے
بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور پھر کہا کہ خدا نے تمہارے لئے اس قبیلہ کے ہر آدمی کے بدلنے میں
اتنا اجر مقرر کیا ہے اور جوش مسرت میں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک پر وا نہ خوشنودی لکھ دیتا ہوں
تا کہ ہمیشہ کے لئے میری یہ خوشنودی تمہارے پاس رہے.چنانچہ آپ نے مجھے ایک پروانہ
لکھ دیا اور اس پر اپنی مہر ثبت فرمائی.“
پھر روایت آتی ہے کہ:
عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَاَصَابَ النَّاسُ حَاجَةً شَدِيدَةً وَجَهْدًا فَأَصَابُوا
غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا فَإِنَّ قُدُورُنَا لَتُغْلِى إِذْجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَمْشِي بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ بِقَوْسِهِ ثُمَّ جَعَلَ يَرْمِلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّهْبَةَ
لَيُسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ -
: ابوداؤد بحوالہ تلخیص الصحاح کتاب الجہاد
: ابوداؤ دوترمذی
Page 366
۳۵۱
یعنی " عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی بیان کرتے
ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ایک موقع پر لوگوں کو خطرناک
بھوک لگی اور وہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا ) جس پر
انہوں نے ایک بکریوں کے گلہ میں سے چند بکریاں پکڑ لیں اور انہیں ذبح کر کے پکانا شروع
کر دیا.ہماری ہنڈیاں اس گوشت سے اہل رہی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے
تشریف لے آئے اور آپ نے آتے ہی اپنی کمان سے ہماری ہنڈیوں کوالٹ دیا اور غصہ
میں گوشت کے ٹکڑوں کو مٹی میں مسلنے لگ گئے اور فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہے.“
یہ ان لوگوں کا قصہ ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کولوٹ مار کی تعلیم دی جاتی تھی.میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کسی یورپین فوج کو اس طرح کی حالت پیش آئے کہ ان کے پاس زادراہ ختم ہو گیا
ہوا اور فوجی لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہوں تو کسی چرتے ہوئے گلہ کی بکریوں پر قبضہ کر لینا تو معمولی بات
ہے وہ نہ معلوم کیا کچھ جائز قرار دے لیں.پھر روایت آتی ہے کہ:
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَهُوَ يَبْتَغِي عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ لَا أَجْرَلَهُ فَدَعَارَلَهُ ثَلَانَّا كُلُّ ذَالِكَ يَقُولُ
لَا أَجْرَلَهُ
و یعنی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے کہ اس کی اصل نیست تو جہاد فی سبیل اللہ کی ہے لیکن
ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال آجاتا ہے کہ جنگ میں کچھ مال و متاع بھی مل رہے گا تو اس میں
کوئی حرج تو نہیں ہے.آپ نے فرمایا.ایسے شخص کے لئے ہرگز کوئی ثواب نہیں ہے.اس شخص
نے حیران ہو کر تین دفعہ اپنا سوال دو ہرایا مگر ہر دفعہ آپ نے یہی جواب دیا کہ اس کے لئے
ہرگز کوئی ثواب نہیں.“
اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کرنے والے کی نیت خالصۂ دینی ہونی چاہئے اور اگر حفاظت
دین کے علاوہ کوئی ذرا سا خیال بھی اس کے دل میں پیدا ہو تو وہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور غنیمت
لے : ابوداؤ دو نسائی
Page 367
۳۵۲
اور دنیوی مال ومتاع کی امید رکھنا مجاہد کے لئے قطعی حرام ہے.پھر روایت آتی ہے کہ:
مَامِنُ غَازِيَةٍ تَغْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلَثَى أَجْرِهِمُ
مِنَ الْآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُمُ التَّلْتُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ اَجُرُهُ
یعنی " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجاہدین خدا کی راہ میں لڑنے کے لئے
نکلتے ہیں اور ان کو لڑائی میں غنیمت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے تو ان کا دو تہائی ثواب آخرت کا کم
ہو جائے گا اور صرف ایک تہائی ثواب ملے گا لیکن اگر انہیں کوئی غنیمت ہاتھ نہ آئے تو ان کو
پورا پورا ثواب ملے گا.“
یہ حدیث گزشتہ حدیث کی نسبت زیادہ واضح ہے کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑائی
میں خالصہ جہاد فی سبیل اللہ کی نیت سے شامل ہوتا ہے اور اس میں کوئی ملونی دنیا کی نہیں ہوتی اور پھر اسے
بغیر خیال اور امید کے غنیمت کا مال بھی مل جاتا ہے تو پھر بھی چونکہ اسے دنیا کے اموال سے حصہ مل گیا ہے
اس لئے اس کا آخرت کا اجر کم ہو جائے گا.لیکن جو شخص خالص جہاد کی نیت سے نکلتا ہے اور اسے غنیمت
کا مال مطلقا نہیں ملتا وہ پورے پورے ثواب کا حق دار ہو گا.گویا جہاں گزشتہ حدیث صحابہ کے دل میں دنیا
کے اموال سے محض عدم رغبت پیدا کرتی تھی وہاں یہ حدیث دوری اور ایک قسم کی نفرت پیدا کرتی ہے
اور اس تعلیم کے ہوتے ہوئے ایک سچا مسلمان نہ صرف یہ کہ غنیمت وغیرہ کا خیال تک دل میں نہیں لائے گا
بلکہ غنیمت کے مواقع سے بھی حتی الوسع پر ہیز کرے گا اور اس کی یہی خواہش اور کوشش ہوگی کہ جس طرح
بھی ہو غنیمت اسے نہ ملے تا کہ جہاد کے ثواب میں کمی نہ آئے.چنانچہ کمز ور لوگوں کو الگ رکھ کر جس کا وجود
کم و بیش ہر قوم میں پایا جاتا ہے مگر جو یقیناً صحابہ کی جماعت میں دنیا کی ہر قوم سے کمتر تعداد میں تھے صحابہ
اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے.چنانچہ ابو داؤد کی روایت میں ہم
دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح مسلم بن حارث نے ایک دشمن قبیلہ پر حملہ کر کے غنیمت حاصل کرنے کی بجائے
اسلام کی تحریک کر کے مسلمان بنالیا اور خود غنیمت سے محروم ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے
فعل کی بہت تعریف فرمائی اور اسے اپنی طرف سے ایک پروانہ خوشنودی عطا فرمایا.پھر ابوداؤد ہی کی روایت ہے کہ جب ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں مدینہ سے
ل مسلم و ابوداؤ دونسائی.الفاظ مطابق ابوداؤد کتاب الجہاد
Page 368
۳۵۳
نکلنے لگے تو ایک بوڑھے انصاری نے ایک غریب صحابی واثلہ بن اسقع کو اپنی طرف سے سواری وغیرہ
کا انتظام کر دیا.جہاد کے بعد واثلہ بن اسقع ، کعب بن عجرة کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ یہ
اونٹنیاں غنیمت میں دی ہیں تم اپنا حصہ لے لو.کعب نے کہا.کبھتیجے ! خدا تمہیں یہ مال مبارک کرے.میری
نیت غنیمت کی نہ تھی بلکہ ثواب کی تھی اور حصہ لینے سے انکار کر دیا.پھر نسائی میں ایک روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعرابی ایمان لایا اور ایک غزوہ
میں ساتھ ہولیا.جب کچھ مال غنیمت ملا تو آپ نے اس کا حصہ بھی نکالا.اسے معلوم ہوا تو وہ آپ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ! آپ نے میرا حصہ نکالا ہے.خدا کی قسم میں تو اس خیال سے
مسلمان نہیں ہوا تھا.میری تو یہ نیت تھی کہ مجھے خدا کی راہ میں ( حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے )اس
جگہ تیر لگے اور میں جنت میں جاؤں.آپ نے فرمایا.اگر یہ شخص سچی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو خدا اسے
پورا کرے گا.تھوڑی دیر بعد لڑائی ہوئی تو وہ شخص وہیں حلق میں تیر کھا کر شہید ہوا.جب صحابہؓ ا سے
آپ کے سامنے اٹھا کر لائے تو آپ نے پوچھا کیا یہ وہی ہے.صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ.آپ
نے فرمایا! ”خدا نے اس کی آرزو کو پورا کر دیا.پھر آپ نے اس کے کفن کے لئے اپنا جبہ عطا کیا اور اس
کے لئے خاص طور پر دعا فرمائی.افسوس صد افسوس! ان شہادتوں کے ہوتے ہوئے بعض لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ پر یہ الزام لگاتے ہوئے خدا کا خوف نہیں کرتے کہ ان لڑائیوں میں ان کی غرض لوٹ مار
اور دنیا کمانا تھی.عرب میں جنگ کا طریق کفار اور مسلمانوں کی لڑائیوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے یہ جاننا بھی
ضروری ہے کہ عرب میں جنگوں کا طریق دورنگ رکھتا تھا جسے انگریزی
میں فیوڈ (FEUD) کہتے ہیں یعنی جب کسی وجہ سے عرب کے دو قبائل میں جنگ چھڑتی تھی تو پھر جب
تک ان میں با قاعدہ صلح نہ ہو جاتی تھی وہ ہمیشہ جنگ کی حالت میں سمجھے جاتے تھے اور موقع پا کر وقفہ وقفہ
لے : ابوداؤد میں اس کا نام مذکور نہیں مگر اسد الغابہ سے پتا لگتا ہے کہ اس کا نام کعب بن عجرہ تھا.: كتاب الجهاد
: كتاب الجنائز
اوپر والی جملہ روایتوں میں جن میں ابواب وغیرہ کا حوالہ نہیں دیا گیا وہ عموماً ابواب الجہاد والسیر والمغازی سے لی گئی
ہیں اور ان کے الفاظ تلخیص الصواح کی روایت کے مطابق درج کئے گئے ہیں.
Page 369
۳۵۴
سے آپس میں لڑتے رہتے تھے.حتیٰ کہ بعض اوقات یہ جنگیں بڑے بڑے لمبے عرصہ تک جاری رہتی
تھیں.چنانچہ جنگ بسوس جس کا ذکر کتاب کے حصہ اول میں گزر چکا ہے اسی طرح وقفہ وقفہ سے چالیس
سال تک جاری رہی تھی اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض جنگیں سو سو سال تک بھی جاری رہیں مگر مسلسل
لڑتے رہنے کا عرب میں دستور نہیں تھا جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اول تو چونکہ قبیلہ کاہر شخص سپاہی ہوتا
تھا اور کوئی باقاعدہ الگ فوج نہیں ہوتی تھی اس لئے قبائل عرب اپنی جنگوں
کو مسلسل طور پر جاری نہیں رکھ
سکتے تھے اور اپنے دوسرے کا روبار کی وجہ سے اس بات پر مجبور تھے کہ وقفہ دے کر لڑائی کریں.دوسرے
چونکہ جنگ میں ہر شخص اپنا اپنا خرج خود برداشت کرتا تھا اور اس غرض کے لئے عموماً کوئی قو می خزا نہ نہیں ہوتا
تھا اس لئے یہ انفرادی مالی بوجھ بھی عربوں کو مجبور کرتا تھا کہ دم لے لے کر میدان میں آئیں.اس غیر مسلسل
جنگ کو جاری رکھنے کے لئے بعض اوقات یہ طریق بھی اختیار کیا جاتا تھا کہ جب ایک لڑائی ہوتی تھی تو اسی
میں آئندہ کے لئے وعدہ ہو جاتا تھا کہ اب فلاں وقت فلاں جگہ پھر ملیں گے اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا
چلا جاتا تھا.چنانچہ احد کے موقع پر ابوسفیان نے اسی قسم کا وعدہ مسلمانوں سے کیا تھا جس کے نتیجہ میں
غزوہ بدر الموعدہ وقوع میں آیا.الغرض عربوں میں مسلسل لڑتے رہنے کا طریق نہیں تھا بلکہ وہ وقفہ
ڈال ڈال کر لڑتے تھے اور درمیانی وقفوں کولڑائی کی تیاری اور اپنے دوسرے کاروبار میں صرف کرتے
تھے اور ان کی یہ ساری لڑائیاں ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہوتی تھیں.یہ ایک بڑا عجیب نکتہ ہے جسے
نظر انداز کر دینے کی وجہ سے بعض مؤرخین نے ٹھو کر کھائی ہے.کیونکہ انہوں نے قریش اور مسلمانوں کی
باہمی لڑائیوں میں سے ہر لڑائی کے لئے الگ الگ وجوہات تلاش کرنی چاہی ہیں.حالانکہ حق یہ ہے کہ
جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان ایک دفعہ جنگ شروع ہو گیا تو پھر اس وقت تک کہ ایک با قاعدہ معاہدہ
کے ذریعہ سے ان کے درمیان صلح نہیں ہوگئی.یعنی صلح حدیبیہ تک جو ہجرت کے چھٹے سال ہوئی یہ دونوں
قو میں حالت جنگ میں تھیں اور اس عرصہ میں ان کے درمیان جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں وہ اسی جنگ کے
مختلف کارنامے تھے اور ان کے لئے الگ الگ وجوہات تلاش کرنا سخت غلطی ہے.ہاں بعض اوقات
بے شک ایسا ہوا ہے کہ کسی درمیانی لڑائی کے لئے کوئی الگ تحریکی باعث بھی پیدا ہو گیا ہے ،لیکن اصل سبب
وہی مستقل پہلا جھگڑا رہا ہے.اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض اوقات عرب کے جنگوں میں یہ بھی ہوتا تھا
اور دراصل یہ بات تو آج کل کے جنگوں میں بھی پائی جاتی ہے ) کہ جنگ کرنے والے قبائل کے ساتھ
Page 370
۳۵۵
دوسرے قبائل بھی اپنے اپنے قومی مصالح کے ماتحت جنگ میں شامل ہو جاتے تھے مثلاً اگر الف اورب
میں جنگ شروع ہوئی تو علاوہ اس کے الف کے حلیف الف کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اورب کے
حلیف ب کے ساتھ.ایسا بھی ہوتا تھا کہ دوران جنگ میں کوئی قبیلہ کسی وجہ سے الف کے ساتھ مل جاتا تھا
اور کوئی دوسرا قبیلہ ب کے ساتھ ہو جاتا تھا اور اس طرح جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا تھا.قریباً قریباً یہی
صورت اسلامی جنگوں میں پیش آئی.یعنی ابتداء مسلمانوں کو قریش مکہ کی طرف سے جنگ کا الٹی میٹم ملا جسے
بالآخر انہوں نے مجبور ہوکر قبول کیا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ بہت سے دوسرے قبائل بھی اس جنگ کی
لپیٹ میں آتے گئے.مثلاً قریش مکہ نے کسی دوسرے قبیلہ کو مسلمانوں کے خلاف اپنے ساتھ گانٹھ لیا تو
مسلمانوں کی اس کے ساتھ بھی جنگ چھڑ گئی یا قریش کے نمونہ کو دیکھ کر کسی دوسرے قبیلہ نے خود بخود
مسلمانوں کے خلاف جارحانہ کارروائی شروع کر دی تو اس سے بھی جنگ کا آغاز ہوگیا یا قریش کی ساز باز
سے کسی حلیف قوم نے مسلمانوں سے دغا بازی کی تو اس طرح اس کے ساتھ بھی مسلمانوں کی لڑائی
ہوگئی.وغیر ذالک.الغرض جب جنگ کی آگ ایک دفعہ مشتعل ہوگئی تو اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا.حتی کہ
ایک تھوڑے عرصہ میں ہی عرب کی سرزمین کے بیشتر حصہ سے اس آگ کے شعلے بلند ہونے لگ گئے.ابتدائی اسلامی جنگوں کے متعلق پوری بصیرت حاصل کرنے کے لئے یہ
جاننا بھی ضروری ہے کہ جیسا کہ مندرجہ بالا قرآنی آیات اور دیگر تاریخی
روایات میں بھی اشارے کئے گئے ہیں یہ اسلامی جنگیں سب ایک قسم کی نہ تھیں بلکہ مختلف قسم کے اسباب
کے ماتحت وقوع میں آئی تھیں مثلاً بعض لڑائیاں دفاع اور خود حفاظتی کی غرض سے تھیں یعنی ان میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو کفار کے مظالم اور تباہی سے بچایا
جاوے.بعض قیام امن کے لئے تھیں یعنی ان کا مقصد ملک میں
فتنہ کو دور کرنا اور امن کو قائم کرنا تھا.بعض
مذہبی آزادی کے قائم کرنے کی غرض سے تھیں.بعض تعزیری رنگ رکھتی تھیں یعنی ان کی غرض و غایت کسی
قوم یا قبیلہ یا گروہ کو ان کے کسی خطر ناک جرم یا ظلم و ستم یا دغا بازی کی سزاد یا تھی.بعض سیاسی تھیں یعنی ان
کا مقصد کسی معاہد قبیلہ کی اعانت یا اس قسم کا کوئی اور سیاسی تقاضا تھا اور بعض ایسی بھی تھیں جن میں ان
اغراض و مقاصد میں سے ایک سے زیادہ اغراض مد نظر تھیں مثلاً وہ دفاعی بھی تھیں اور تعزیری بھی یا سیاسی
بھی تھیں اور قیام امن کی غرض بھی رکھتی تھیں.وغیر ذالک.یہ ایک بڑا ضروری علم ہے جس کے نہ جاننے کی
وجہ سے بعض مؤرخین نے ساری لڑائیوں کو ایک ہی غرض کے ماتحت لانے کی کوشش کی ہے اور پھر ٹھوکر کھائی
اسلامی جنگوں کے اقسام
Page 371
۳۵۶
ہے.اس جگہ یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ اوپر کی بحث میں ہم نے عام طور پر صرف دفاع اور خود حفاظتی
کی غرض کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کی ابتداء زیادہ تر اسی غرض کے ماتحت ہوئی تھی جیسا کہ
ابتدائی قرآنی آیت سے ظاہر ہے اور باقی اغراض بعد میں آہستہ آہستہ حالات کے ماتحت پیدا ہوتی گئیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کا بیان شروع کرنے سے قبل مناسب
اسلامی آداب جہاد
معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ مختصر طور پر وہ آداب بھی بیان کر دئے جائیں جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جہاد میں ملحوظ رکھتے تھے اور جن کی صحابہ کو تاکید کی جاتی تھی.یہ آداب
عموماً صحاح ستہ کی کتب الجهاد والسیر والمغازی سے ماخوذ ہیں.اور اس لئے میں نے صرف ان باتوں
کا حوالہ درج کیا ہے جو یا تو بہت اہم ہیں اور یا نسبتاً کم معروف ہیں اور باقی کے حوالے کی ضرورت نہیں
سمجھی.سو جاننا چاہئے کہ:
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفروں کو حتی الوسع جمعرات کے دن شروع کرنا پسند فرماتے تھے
-٢
-٣
-
اور گھر سے
عموماً صبح کے وقت نکلتے تھے.روانگی سے قبل دعا کرنا آپ کی سنت تھی.دشمن کی حرکات و سکنات کا علم حاصل کرنے کے لئے آپ خبر رسانی کا پختہ انتظام رکھتے تھے اور
عام طور پر خبر رسانوں کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ جب کوئی خبر لائیں تو عام مجلس میں اس کا ذکر نہ
کریں اور اگر کوئی تشویشناک خبر ہوتی تھی تو آپ پھر خود بھی اس کا عام اظہار نہیں فرماتے
تھے.البتہ خاص خاص صحابہ کو اس کی اطلاع دے دیتے تھے.لے
جب آپ کسی جنگی غرض سے نکلتے تھے تو آپ کا یہ عام طریق تھا کہ اپنی منزل مقصود کا علم نہیں
دیتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی کرتے تھے کہ اگر مثلاً جنوب کی طرف جانا ہوتا تھا تو چند
میل شمال کی طرف جا کر پھر چکر کاٹ کر جنوب کی طرف گھوم جاتے تھے.آپ کی عادت تھی کہ شہر سے تھوڑی دور نکل کر فوج کا جائزہ لیا کرتے تھے اور سب انتظام ٹھیک
ٹھاک کرنے کے بعد آگے روانہ ہوتے تھے.جب کوئی اہم مہم پیش آتی تھی تو آپ اس کے لئے صحابہ میں تحریک فرماتے تھے پھر جو لوگ اس
ا : زرقانی حالات غزوہ اُحد و خندق
: بخاری حالات غزوہ تبوک و زرقانی حالات غزوہ بنولحیان
Page 372
۳۵۷
کے لئے تیار ہوتے تھے وہ اپنا اپنا سامان جنگ اور سواری وغیرہ کا انتظام خود کرتے تھے.البتہ کسی
ذی ثروت صحابی کو مقدرت ہوتی تھی تو وہ دوسروں کی امداد بھی کر دیتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم عموماً اس قسم کی امداد کی تحریک فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات جب گنجائش ہوتی تھی تو خود
بھی امداد فرماتے تھے.چھوٹے بچے یعنی پندرہ سال سے کم عمر کے بچے عموماً جنگ میں ساتھ نہیں لئے جاتے تھے اور جو
بچے اس شوق میں ساتھ ہو لیتے تھے انہیں جائزہ کے وقت جو عموماً شہر سے باہر نکل کر لیا جاتا
تھا واپس کر دیا جاتا تھا.جنگ میں عموماً چند ایک عورتیں بھی ساتھ جاتی تھیں جو کھانے پینے کا انتظام کرنے کے علاوہ
تیمار داری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام بھی کرتی تھیں اور لڑائی کے وقت فوجیوں کو پانی بھی لا کر
دیتی تھیں.بعض خاص خاص موقعوں پر مسلمان عورتوں نے کفار کے خلاف تلوار بھی چلائی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ سفر میں اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو یا ایک سے
زیادہ کو جیسا کہ موقع ہوا اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کے لئے آپ قرعہ ڈالا کرتے تھے اور جس
کا نام قرعہ میں نکلتا تھا اسے ساتھ لے جاتے تھے.جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام طریق تھا کہ جب کبھی آپ کو کسی دشمن قبیلہ کے متعلق
یہ اطلاع ملتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو آپ پیش دستی کر کے
اس کے حملہ کو روکنے کی کوشش فرماتے تھے اور ایسا نہیں کرتے تھے کہ دشمن کو پوری طرح تیاری
کر لینے کا موقع دیں اور اس کے حملہ کا انتظار کرتے رہیں اور جب وہ عملاً حملہ کر دے تو پھر اس کا
مقابلہ کریں.نیز آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسلامی لشکر دشمن تک اچانک پہنچ جائے اور اسے
اطلاع نہ ہو.ان تدابیر سے آپ نے مسلمانوں کو بہت سے مصائب سے بچالیا.جب آپ کوئی فوجی دستہ روانہ فرماتے تھے تو انہیں چلتے ہوئے یہ نصیحت فرماتے تھے کہ جب تم
دشمن کے سامنے ہو تو اسے تین باتوں کی طرف دعوت دو.اور اگر ان باتوں میں سے وہ کوئی ایک
بات بھی مان لے تو اسے قبول کر لو اور لڑائی سے رک جاؤ.سب سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دو
اگر وہ لوگ مسلمان ہونا پسند کریں تو پھر انہیں ہجرت کرنے کی تحریک کرو.اگر وہ ہجرت کرنا قبول
نہ کریں تو ان سے کہو کہ اچھا تم مسلمان رہو اور اپنے گھروں میں ٹھہر ولیکن اگر وہ مسلمان ہونا ہی
-^
- 1+
-11
Page 373
۳۵۸
-۱۲
پسند نہ کریں تو پھر ان سے کہو کہ اپنے مذہب پر رہو لیکن مسلمانوں کی عداوت اور ان سے جنگ کرنا
چھوڑ دو اور اسلامی حکومت کے ماتحت آ جاؤ.اگر وہ لوگ یہ بھی نہ مانیں تو پھر اس کے بعد تمہیں
ان سے لڑنے کی اجازت ہے.نیز جب آپ کوئی فوجی دستہ روانہ فرماتے تھے تو اسے نصیحت فرماتے تھے کہ اُغْرُوا بِسْمِ اللهِ
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْداً وَلَا امْرَأَةً
وَلَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَاطِفْلاً وَلَا صَغِيراً وَلَا
اِمْرَأَةً وَاصْلِحُوا وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ " یعنی اے مسلمانو! نکلو اللہ کا نام
لے کر اور جہاد کر و حفاظت دین کی نیت سے.مگر خبر دار مال غنیمت میں بد دیانتی نہ کرنا اور نہ کسی
قوم سے دھو کہ کرنا.اور نہ دشمنوں کے مقتولوں کا مثلہ کرنا اور نہ بچوں اور عورتوں اور مذہبی عبادت
گاہوں کے لوگوں
کو قتل کرنا اور نہ بہت بوڑھوں
کو قتل کرنا اور ملک میں اصلاح کرنا.اور لوگوں کے
ساتھ احسان کا معاملہ کرنا.کیونکہ تحقیق خدا تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا
ہے.اور حضرت ابوبکر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب کسی فوج کو روانہ فرماتے تھے تو اس کے امیر
کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ الَّذِيْنَ زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ فَذَرْهُمْ وَمَا
زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَراً مُشْمِراً وَلَا تُخْرِبَنَّ عَامِراً -
یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے خیال میں اپنے آپ کو خدا کی عبادت کے لئے وقف کر رکھا ہے
ان کو کچھ نہ کہنا اور اسی طرح جس چیز کو وہ مقدس سمجھتے ہوں اسے بھی کچھ نہ کہنا اور پھل دار درخت
کو نہ کاٹنا اور نہ کسی آبادی کو ویران کرنا.“
یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ بعض اوقات لڑائی میں دشمن کے بچوں اور بوڑھوں
اور عورتوں کو قتل کر دیتے تھے اور بعض اوقات نہایت بے رحمی کے ساتھ دشمن کے مقتولوں کے ہاتھ پاؤں
اور ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالتے تھے جسے مُثلہ کرنا کہتے تھے اور دشمن کے اموال و امتعہ اور ان کی آبادی
کو تباہ وبرباد کر دیتے تھے اور عہد و پیمان کی تو کوئی قیمت ہی نہ تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب
باتوں سے روک دیا.مذہبی لوگوں اور مذہبی چیزوں کی حفاظت کے طریق میں بھی اسلام نے ایک نمایاں
ا : مسلم وابوداؤد
ابوداؤد
: مسلم
ے : طحاوی
هه : موطا امام مالک
Page 374
۳۵۹
امتیاز پیدا کیا.بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب کسی جماعت کو روانہ فرماتے تھے تو اسے نصیحت
فرماتے تھے کہ بَشِّرُوا وَلا تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسّرُوا یعنی ”لوگوں کو خوشخبریاں دو یعنی ان
کو خوش رکھنے کی کوشش کرو اور ایسا طریق اختیار نہ کر وجس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہواوران کے
لئے آسانیاں پیدا کرو اور انہیں مشکلوں میں مت ڈالو.“
-١٣
- ۱۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لازمی طریق تھا کہ جب کسی پارٹی یا دستہ یا فوج کو روانہ فرماتے تھے
تو ان میں سے کسی شخص کو ان کا امیر مقرر فرما دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر تین آدمی بھی ہوں
تو انہیں چاہئے کہ اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر بنالیا کریں اور آپ امیر کی اطاعت کی سخت تاکید
فرماتے تھے.حتی کہ فرمایا کہ اگر کوئی تم پر ایک بیوقوف حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جاوے تو
اس کی پوری پوری اطاعت کرو.مگر ساتھ ہی یہ حکم تھا کہ اگر امیر کوئی ایسا حکم دے جو خدا اور اس
کے رسول کے حکم کے صریح خلاف ہو تو اس معاملہ میں اس کی اطاعت نہ کرو مگر اس حال میں
بھی اس کا ادب ضرور ملحوظ رکھو.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب کسی غزوہ میں کسی چڑھائی پر چڑھتے تھے تو
تکبیر کہتے جاتے تھے یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے اور جب کسی بلندی سے نیچے اترتے تھے تو
تسبیح کہتے تھے یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے.۱۵ سفر میں صحابہ کو حکم ہوتا تھا کہ اس طرح پر پڑاؤ نہ ڈالا کریں کہ لوگوں کے لئے موجب تکلیف ہو
نیز حکم تھا کہ کوچ کے وقت اس طرح نہ چلا کرو کہ راستہ رک جاوے اور اس میں یہاں تک سختی
فرماتے تھے کہ ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ جو شخص پڑاؤ اور رستے میں دوسروں کا خیال نہیں رکھے گا
وہ جہاد کے ثواب سے محروم رہے گا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کے سامنے ہوتے تھے تو پہلے ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے.لڑائی کے لئے آپ صبح کا وقت پسند فرمایا کرتے تھے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو رک جاتے
تھے اور پھر دو پہر گزار کرلڑائی کا حکم دیتے تھے.کے
-17
-12
-۱۸
لڑائی سے قبل آپ خود صحابہ کی صف آرائی فرمایا کرتے تھے اور صفوں میں بے ترتیبی کو بہت
نا پسند فرماتے تھے.: مسلم
: ابوداؤد
: ابوداؤ دوترندی
Page 375
۳۶۰
۱۹ اسلامی لشکر کے ساتھ عموماً دو قسم کے جھنڈے ہوتے تھے ایک سفید ہوتا تھا جو کسی لکڑی وغیرہ پر
لپٹا ہوتا تھا اسے لوا کہتے تھے.دوسرا عموماً سیاہ ہوتا تھا جس کی ایک طرف کسی لکڑی وغیرہ سے
بندھی ہوتی تھی اور وہ ہوا میں لہراتا تھا اسے رایہ کہتے تھے.یہ دونوں قسم کے جھنڈے لڑائی کے
وقت خاص خاص آدمیوں کے سپر د کر دئے جاتے تھے.-۲۰
-۲۱
-۲۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموما ہرلڑائی میں اپنی فوج کا کوئی لفظی شعار مقررفرما دیا کرتے تھے
جس سے اپنا بیگا نہ پہچانا جاتا تھا.فوج میں شور و شغب کو نا پسند کیا جاتا تھا اور نہایت خاموشی کے ساتھ کام کرنے کا حکم تھا.لڑائی سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج کے مختلف دستوں پر مختلف صحابیوں کو
امیر مقرر کر کے ان کی جگہیں متعین فرما دیتے تھے اور فرائض سمجھا دیتے تھے.ان کمانڈروں کے
تقرر میں عموماً اس اصول کو مدنظر رکھا جاتا تھا کہ کسی دستہ پر اس شخص کو امیر بنایا جاوے جوان
میں صاحب اثر ہو.۲۳- بعض خاص خاص موقعوں پر آپ کا یہ بھی طریق تھا کہ صحابہ سے خاص بیعت لیتے تھے.چنانچہ
صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لینے کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے.- ۲۴
- ۲۵
میدان جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں لڑائی
شروع نہ کی جاوے.لڑائی کے دوران میں بھی آپ خاص خاص احکام جاری فرماتے رہتے تھے اور خود یا کسی بلند آواز
صحابی کے واسطے سے پکار پکار کر ضروری ہدایات کا اعلان فرماتے تھے.۲۶.مسلمانوں کو بھاگنے یا ہتھیار ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی.حکم تھا کہ یا غالب آؤ یا شہید
ہو جاؤ.ہاں جنگی اغراض کے لئے وقتی طور پر پیچھے ہٹ آنے کی اجازت تھی.تا لیکن اگر کبھی کسی
بشری کمزوری کے ماتحت بعض لوگ بھاگ جاتے تھے تو آپ ان سے زیادہ ناراض نہیں ہوتے
تھے بلکہ انہیں آئندہ کے لئے ہمت دلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ شاید تم لوگ جنگی تدبیر کے طور پر
دوبارہ حملہ کرنے کے لئے پیچھے ہٹ آئے ہو گے.: ابوداؤد
Watchword L
:
12.19:
سے : سورۃ انفال
Page 376
۳۶۱
-۲۷
- ۲۸
صحابہ کوحکم تھا کہ لڑائی میں کسی کے منہ پر ضرب نہ لگا ئیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ضرب لگانے میں سب لوگوں سے زیادہ نرم مسلمان
کو ہونا چاہئے.۲۹ تاکیدی حکم تھا کہ جب تک عملاً لڑائی نہ ہوئے.قیدی نہ پکڑے جائیں.یہ نہیں کہ دشمن کو
ھاک تک مالائی نہ ہوے قیدی نہ جائیں.یہ
دیکھا اور کمزور پا کر قیدی پکڑنے شروع کر دئے.-۳۲
حکم تھا کہ جو قیدی پکڑے جائیں انہیں بعد میں حسب حالات یا تو بطور احسان کے یونہی چھوڑ دیا
جاوے یا ضروری ہو تو قید میں رکھا جاوے، مگر یہ قید صرف اس وقت رہ سکتی ہے کہ جب تک جنگ
جاری رہے یا جنگ کی وجہ سے جو بوجھ پڑے ہوں وہ دور نہ ہو جائیں، اس کے بعد نہیں ہے
قیدیوں کے ساتھ نہایت درجہ نرمی اور شفقت کے سلوک کا حکم تھا.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے صحابہ کو خود اپنے آرام کی نسبت بھی قیدیوں کے آرام
کا خیال زیادہ رہتا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم تھا کہ جو قیدی آپس میں قریبی رشتہ دار
ہوں ان کو ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ کیا جاوے.قیدیوں کا فدیہ صرف نقدی کی صورت میں لینے پر اصرار نہ کیا جاتا تھا.چنانچہ بدر کے بعض خواندہ
قیدیوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھوتہ کیا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کو نوشت و خواند
سکھا دیں تو انہیں چھوڑ دیا جاوے گا.بعض اوقات کفار قیدیوں کو مسلمان قیدیوں کے تبادلہ میں بھی
چھوڑ دیا جاتا تھا.نقد فدیہ کی صورت میں بھی مکاتبت کے طریق کی اجازت تھی.۳۳.مسلمانوں کو لوٹ مار اور غارت گری سے نہایت سختی سے روکا جا تا تھا.چنانچہ اس کے متعلق کسی
قدر مفصل بحث او پر گزر چکی ہے.-۳۴
حکم تھا کہ اگر لڑائی کے وقت بھی کوئی دشمن اسلام کا اظہار کرے تو خواہ اس نے مسلمانوں کا کتنا ہی
نقصان کیا ہو فوراً اس سے ہاتھ کھینچ لو.کیونکہ اب اس سے خطرہ کا احتمال نہیں رہا.چنانچہ اس ضمن
میں اسامہ بن زید کا واقعہ او پرگز را ہے.ل : بخاری و مسلم
۳ : سورۃ انفال : ۶۸
ه: ترمذی ابواب السير وابواب البيوع
: ابوداؤد
: سورة محمد : ۵
Page 377
۳۶۲
- ۳۵
عہد و پیمان کے پورا کرنے کی نہایت سختی سے تاکید کی جاتی تھی اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو عہد کا اس قدر پاس تھا کہ جب حذیفہ بن یمان مکہ سے ہجرت کر کے بدر کے موقع پر آپ کی
خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں جب مکہ سے نکلا تھا تو قریش نے
یہ شبہ کر کے کہ شاید میں آپ کی مدد کے لئے جارہا ہوں مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ میں آپ کی طرف
سے نہ لڑوں گا.تو آپ نے فرمایا تو پھر تم جاؤ اور اپنا عہد پورا کرو ہمیں خدا کی امداد بس ہے.یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال احتیاط تھی.حالانکہ فتویٰ کے طور پر ایسا عہد جو جبر کے طور پر
حاصل کیا جاوے واجب الا یفا نہیں ) اور حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں تو یہاں تک اعلان
کیا تھا کہ جو مسلمان دشمن کے ساتھ دھوکا یا بدعہدی کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا.- میدان جنگ میں جو مسلمان شہید ہوتے تھے انہیں غسل نہیں دیا جا تا تھا اور نہ ہی خاص طور پر
کفنایا جاتا تھا.۳۷.مجبوری کے وقت ایک ہی قبر میں کئی کئی شہداء کو اکٹھا دفن کر دیا جاتا تھا اور ایسے موقعوں پر ان
لوگوں کو قبر میں پہلے اتارا جاتا تھا جو قرآن شریف زیادہ جانتے تھے.نیز شہداء کے متعلق حکم تھا
-۳۸
-
کہ انہیں میدان جنگ میں ہی دفنا دیا جاوے.شہداء کا جنازہ بعض اوقات تو لڑائی کے فوراً بعد پڑھ دیا جاتا تھا اور بعض اوقات جب امن کی
صورت نہ ہو تو بعد میں کسی اور موقع پر پڑھا دیا جاتا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ حتی الوسع دشمن کے مقتولوں کو بھی اپنے انتظام میں دفن
کروادیتے تھے.اسلامی جنگوں میں لڑنے والے تنخواہ دار نہیں ہوتے تھے.۴۱ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ اصول تھا کہ سب سے پہلے امیر لشکر غنیمت کے مال میں سے کوئی ایک
چیز اپنے لئے چن لیتا تھا جسے صفیہ کہتے تھے.پھر سارے اموال کا پانچواں حصہ خدا اور اس کے
رسول کے لئے الگ کر دیا جاتا تھا.اور اس کے بعد بقیہ مال فوج میں بحصہ برابر تقسیم کر دیا جاتا
تھا اس طرح پر کہ سوار کو پیدل کی نسبت دو حصے زیادہ دیا جاتا تھا اور نیز مقتول کا فر کا ذاتی سامان جو
ل : سورۃ انفال : ۷۳ و بنی اسرائیل: ۳۵ و نیز بخاری ومسلم
: مسلم
موطا
دارقطنی بحوالہ الروض الانف حالات غزوہ بدر
Page 378
۳۶۳
اس کے جسم پر ہو وہ بھی مسلمان قاتل کا حق سمجھا جاتا تھا.۴۲ - جو شمس خدا اور اس کے رسول کے لئے الگ کیا جا تا تھا اس میں کچھ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اہل وعیال اور اقرباء میں تقسیم فرما دیتے تھے اور بیشتر حصہ اس کا مسلمانوں کی اجتماعی دینی
اور قومی اغراض میں صرف ہوتا تھا اور اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے
فرمایا کہ مال غنیمت میں سے مجھے خمس کے علاوہ ایک اونٹ کے بال کے برابر بھی لینا حرام ہے
- ۴۳
وَالْخُمْسُ مَرُدُودٌ عَلَيْكُمْ.اور پھر یہ مس بھی تمہارے ہی کام آتا ہے.لڑائی کے میدان میں عام طور پر نماز کی ادائیگی کا یہ طریق تھا کہ امام تو ایک ہی رہتا تھا لیکن
فوج کے آدمی مختلف حصوں میں باری باری آکر امام کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے اور بقیہ
فوج دشمن کے سامنے رہتی تھی اسے صلوٰۃ خوف کہتے ہیں اور مختلف حالات کے ماتحت اس کی
مختلف صورتیں تھیں.-۲۴ شروع شروع میں بعض صحابہ سفروں میں روزے رکھتے تھے اور بعض افطار کرتے تھے لیکن آخری
ایام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جاوے اور فرمایا تھا
کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے.جن صحابہ نے آپ کے اس حکم کو محض ایک
سفارش سمجھ کر روزہ رکھ لیا ان کے متعلق آپ نے فرمایا: أُولئِكَ العُصَاةُ ـ یعنی یہ لوگ
نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہیں.۴۵- جاسوس کے قتل کا عرب میں دستور تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا.۴۶.دشمن کے قاصد کو روک لینے یا کسی قسم کا نقصان پہنچانے یا قتل کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سختی سے منع فرماتے تھے.چنانچہ ایک دفعہ بعض لوگ کفار کے قاصد ہو کر آئے اور انہوں نے آپ
کے سامنے گستاخانہ طریق سے باتیں کیں.آپ نے فرمایا تم قاصد ہو اس لئے میں تمہیں کچھ
نہیں کہہ سکتا.ایک اور موقع پر ایک قاصد آیا اور آپ سے مل کر مسلمان ہوگیا اور پھر اس نے آپ
سے عرض کیا کہ میں اب واپس جانا نہیں چاہتا.آپ نے فرمایا.میں بدعہدی کا مرتکب نہیں
ہوسکتا.تم قاصد ہو تمہیں بہر حال واپس جانا چاہئے.ہاں اگر پھر آنا چا ہو تو آ جانا.چنانچہ وہ گیا
اور کچھ عرصہ کے بعد موقع پا کر پھر واپس آ گیا.تے
ل : موطا امام مالک
: ترمذی ابواب الصوم ے : ابوداؤد کتاب الجہاد
Page 379
۳۶۴
۴۷.جب مکہ اور مدینہ کی سرزمین شرک کے عصر سے پاک ہوگئی اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ اگر
اب بھی کوئی بیرونی مشرک مذہبی تحقیق کے لئے حجاز میں آنا چاہے تو بخوشی آسکتا ہے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس کی حفاظت اور پر امن واپسی کے ہم ذمہ وار ہوں گے.لے
۴۸.کفار میں سے جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے ان کی حفاظت اور حقوق کا آپ
کو خاص خیال رہتا تھا.چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مَنْ قَتَلَ مُـعَـاهِداً لَمْ يَرِحُ رَائِحَةَ
الْجَنَّةِ یعنی جو مسلمان کسی معاہد کا فر کو قتل کرے گا اسے جنت کی ہوا تک نہیں پہنچے گی.نیز آپ نے یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ جو مسلمان کسی معاہد کا فر کو یونہی غلطی سے بلا ارادے کے قتل
کر دے اس کا فرض ہوگا کہ اس کے رشتہ داروں کو اس کی پوری پوری دیت ادا کرنے کے علاوہ
ایک غلام آزاد کرے.۴۹ معاہد کا فر کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِداً أَوِ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ الطَّاقَةِ
أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ فَاَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " یعنی جو مسلمان کسی
معاہد کا فر پر کسی قسم کا ظلم کرے گا یا اسے نقصان پہنچائے گایا اس پر کوئی ایسی ذمہ داری یا ایسا کام
ڈالے گا جو اس کی طاقت سے باہر ہے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی خوشی اور مرضی کے لے
گا تو اے مسلمانو ! سن لو میں قیامت کے دن اس معاہد کا فر کی طرف سے ہو کر اس مسلمان کے
خلاف انصاف چاہوں گا.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے خلاف جنگ کرنے کو نکلتے تھے تو فتح حاصل ہونے کے
بعد عموماً تین دن سے زیادہ وہاں نہیں ٹھہرتے تھے اور یہ غالبا اس لئے کرتے تھے کہ وہاں کے
لوگوں کے لئے اسلامی لشکر کا قیام موجب تکلیف اور پریشانی نہ ہو.۵۱ سب سے آخر میں مگر غالبا سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاد میں دین کی حفاظت اور فتنہ کے سدباب کے
سوا کسی اور نیت کو سخت نا جائز سمجھا جاتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اعلان تھا کہ جو شخص
غنیمت کے لالچ میں یا لڑائی کے اظہار کے لئے یا کسی اور دنیا وی غرض سے نکلتا ہے وہ جہاد کے
ثواب سے قطعی محروم ہے.اس ضمن میں کسی قدر مفصل بحث او پر گزر چکی ہے.-۵۰
لے : سورۃ توبہ
ابوداؤد
: بخاری کتاب الجہاد ۳ : سورۃ نساء : ۹۳
۵ : بخاری کتاب الجهاد
Page 380
۳۶۵
اس جگہ یہ ذکر بھی بے موقع نہ ہو گا کہ اس زمانہ میں عرب میں لڑنے کا طریق یہ ہوتا تھا کہ جب فوجیں
ایک دوسرے کے سامنے ہو جاتیں تھیں تو خاص خاص لوگ انفرادی مقابلوں کے لئے نکل کر مبارز طلبی
کرتے تھے اور ان انفرادی مقابلوں کے بعد عام حملہ کیا جاتا تھا.جنگ میں پیدل اور گھوڑے پر سوار
ہو کر دونوں طرح لڑنے کا دستور تھا مگر گھوڑے پر سوار ہو کر لڑنا بہتر سمجھا جاتا تھا.اونٹ عموماً صرف سفر
کاٹنے یا اسباب اٹھانے کے لئے استعمال کئے جاتے تھے.آلات حرب حملہ کے لئے تلوار، نیزہ اور تیر
کمان تک محدود تھے اور دفاع کے لئے ڈھال اور زرہ اور خود استعمال کئے جاتے تھے.عرب کے بعض
قبائل میں دشمن پر پتھر کی بارش برسانے کے لئے ایک قسم کی مشین بھی استعمال ہوتی تھی جسے منجنیق کہتے
تھے.اس مشین کا خیال غالبا امیر ان سے عرب میں آیا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال
محاصرہ طائف کے موقع پر فرمایا تھا.آغاز جہاد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاطی تدابیر یہ بتایا جا چکا ہے کہ جہاد
بالسیف کی اجازت میں
پہلی قرآنی آیت بارہ صفر ۲ ہجری کو نازل ہوئی تھی.یعنی دفاعی جنگ کے اعلان کا جو خدائی اشارہ ہجرت
میں کیا گیا تھا اس کا با ضابطہ اعلان صفر۲ ہجری میں کیا گیا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کی ابتدائی
کارروائیوں سے فارغ ہو چکے تھے اور اس طرح جہاد کا آغاز ہو گیا.تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ کفار کے
شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء چار تدابیر اختیار کیں جو آپ
کی اعلیٰ سیاسی قابلیت اور جنگی دور بینی کی ایک بین دلیل ہیں.یہ تدابیر مندرجہ ذیل تھیں.اوّل آپ نے خود سفر کر کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ باہمی امن وامان کے معاہدے کرنے
شروع کئے تاکہ مدینہ کے اردگرد کا علاقہ خطرہ سے محفوظ ہو جائے.اس امر میں آپ نے خصوصیت کے
ساتھ ان قبائل کو مدنظر رکھا جو قریش کے شامی رستے کے قرب و جوار میں آباد تھے کیونکہ جیسا کہ ہر شخص سمجھ
سکتا ہے یہی وہ قبائل تھے جن سے قریش مکہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ مدد لے سکتے تھے اور جن کی دشمنی
مسلمانوں کے واسطے سخت خطرات پیدا کر سکتی تھی.دوم آپ نے چھوٹی چھوٹی خبر رساں پارٹیاں مدینہ کے مختلف جہات میں روانہ کرنی شروع
فرمائیں تا کہ آپ کو قریش اور ان کے خلفاء کی حرکات و سکنات کا علم ہوتا رہے اور قریش کو بھی یہ خیال
Page 381
۳۶۶
رہے کہ مسلمان بے خبر نہیں ہیں اور اس طرح مدینہ اچانک حملوں کے خطرات سے محفوظ ہو جائے.سوم ان پارٹیوں کے بھجوانے میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ تا اس ذریعہ سے مکہ اور اس کے گردونواح
کے کمزور اور غریب مسلمانوں کو مدینہ کے مسلمانوں میں آملنے کا موقع مل جاوے.ابھی تک مکہ کے علاقہ
میں کئی لوگ ایسے موجود تھے جو دل سے مسلمان تھے مگر قریش کے مظالم کی وجہ سے اپنے اسلام
کا بر ملا طور پر اظہار نہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے ان میں ہجرت کی طاقت
تھی کیونکہ قریش ایسے لوگوں کو ہجرت سے جبرا روکتے تھے.چنانچہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا
مِن لَّدُنكَ نَصِيرًان یعنی ”اے مومنو! کوئی وجہ نہیں کہ تم لڑائی نہ کرو اللہ کے دین کی حفاظت کے لئے
اور ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو کمزوری کی حالت میں پڑے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ
اے ہمارے رب ! نکال ہم کو اس شہر سے جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہم ناتوانوں کے لئے اپنی
طرف سے کوئی دوست و مددگار عطا فرما.پس ان پارٹیوں کے بھجوانے میں ایک یہ مصلحت بھی تھی کہ تا
ایسے لوگوں کو ظالم قوم سے چھٹکارا پانے کا موقع مل جاوے.یعنی ایسے لوگ قریش کے قافلوں کے ساتھ
ملے ملائے مدینہ کے قریب پہنچ جائیں اور پھر مسلمانوں کے دستے کی طرف بھاگ کر مسلمانوں میں
آملیں.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ پہلا دستہ ہی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن الحارث
کی سرداری میں روانہ فرمایا تھا اور جس کا عکرمہ بن ابو جہل کے ایک گروہ سے سامنا ہو گیا تھا اس میں مکہ
کے دو کمزور مسلمان جو قریش کے ساتھ ملے ملائے آگئے تھے، قریش کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آملے تھے.چنانچہ روایت آتی ہے کہ:
فَرَّمِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ المِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو حَلِيْفٌ بُنُ زَهْرَةَ وَعُتُبَةُ بْنُ
غَزْوَانَ حَلِيْفٌ بَنِي نَوْفَلَ وَكَانَا مُسْلِمَيْنِ وَلَكِنَّهُمَا خَرَجَايَتَوَصَّلَانِ بِالْكُفَّارِ إِلَى
الْمُسْلِمِين - یعنی ” اس مہم میں جب مسلمانوں کی پارٹی لشکر قریش کے سامنے آئی تو دو شخص مقداد بن
عمر و اور عتبہ بن غزوان جو بنو زہرہ اور بنو نوفل کے حلیف تھے مشرکین میں سے بھاگ کر مسلمانوں میں
آملے اور یہ دونوں شخص مسلمان تھے اور صرف کفار کی آڑ لے کر مسلمانوں میں آملنے کے لئے نکلے
طبری وابن ہشام حالات سریہ عبیدة الحارث
: سورۃ النساء : ۷۶
Page 382
۳۶۷
تھے.پس ان پارٹیوں کے بھجوانے میں ایک غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ تا ایسے لوگوں
کو ظالم قریش سے چھٹکارا پانے اور مسلمانوں میں آملنے کا موقع ملتا ر ہے.چہارم : چوتھی تدبیر آپ نے یہ اختیار فرمائی کہ آپ نے قریش کے ان تجارتی قافلوں کی روک تھام
شروع فرما دی جو مکہ سے شام کی طرف آتے جاتے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے.کیونکہ (الف) یہ قافلے جہاں جہاں سے گزرتے تھے مسلمانوں کے خلاف عداوت کی آگ لگاتے جاتے
تھے اور ظاہر ہے کہ مدینہ کے گردونواح میں اسلام کی عداوت کا تختم بویا جانا مسلمانوں کے لئے نہایت
خطر ناک تھا.(ب) یہ قافلے ہمیشہ مسلح ہوتے تھے اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کے قافلوں کا مدینہ سے
اس قدر قریب ہو کر گزرنا ہرگز خطرہ سے خالی نہیں تھا.(ج) قریش کا گزارہ زیادہ تر تجارت پر
تھا اور اندریں حالات قریش کو زیر کرنے اور ان کو ان کی ظالمانہ کارروائیوں سے روکنے اور صلح پر مجبور
کرنے کا یہ سب سے زیادہ یقینی اور سریع الاثر ذریعہ تھا کہ ان کی تجارت کا راستہ بند کر دیا جاوے.چنانچہ
تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن باتوں نے بالآخر قریش کو صلح کی طرف مائل ہونے پر مجبور کیا ان میں ان
کے تجارتی قافلوں کی روک تھام کا بہت بڑا دخل تھا.پس یہ ایک نہایت دانشمندانہ تد بیر تھی جو اپنے وقت پر
کامیابی کا پھل لائی.(د) قریش کے ان قافلوں کا نفع بسا اوقات اسلام کو مٹانے کی کوشش میں صرف ہوتا
تھا بلکہ بعض قافلے تو خصوصیت کے ساتھ اسی غرض سے بھیجے جاتے تھے کہ ان کا سارا نفع مسلمانوں کے
خلاف استعمال کیا جائے گا.اس صورت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان قافلوں کی روک تھام خود اپنی ذات
میں بھی ایک بالکل جائز مقصود تھی.بعض متعصب عیسائی مؤرخین نے جن کو اسلام کی خوبیاں بھی بدی کی شکل میں نظر آتی ہیں یہ اعتراض
کیا ہے کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قریش کے قافلوں کولوٹنے کی غرض سے
نکلتے تھے.ہم ان عدل و انصاف کے مجسموں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا تمہاری قو میں جنہیں تم تہذیب و
شرافت کے معراج کو پہنچا ہوا سمجھتے ہو جنگ کے زمانہ میں دشمن قوموں کے تجارتی رستے نہیں روکتیں ؟ اور
کیا انہیں جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ فلاں دشمن قوم کا کوئی تجارتی جہاز فلاں جگہ سے گزر رہا ہے تو وہ فوراً اس
کے پیچھے ایک بحری دستہ روانہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دینے یا اسے مغلوب کر کے اس کے اموال پر قبضہ
کر لینے کی تدابیر نہیں اختیار کرتیں؟ تو پھر کیا اس وجہ سے تمہارے فرمانرواؤں کا نام ڈاکو اور لٹیرے
اور غارت گر رکھا جاسکتا ہے؟ یقینا اگر مسلمانوں نے قریش کے قافلوں کی روک تھام کی تو اس غرض سے
Page 383
۳۶۸
نہیں کی کہ ان کے قافلوں کے اموال پر قبضہ کریں بلکہ اس لئے کی کہ تدابیر جنگ کا تقاضا تھا کہ قریش کی
تجارت کا رستہ بند کر دیا جاوے کیونکہ اس سے بہتر ان کو ہوش میں لانے اور صلح کی طرف مائل کرنے کا
اور کوئی ذریعہ نہ تھا.باقی اگر قریش کا کوئی قافلہ مغلوب ہو گیا اور اس غلبہ کے نتیجہ میں اس کا مال و متاع
مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو وہ جنگ کی فتوحات کا حصہ تھا جس کا ہر قوم اور ہر زمانہ میں فاتح کو حق دار سمجھا گیا
ہے.کیا معترضین کا یہ مطلب ہے کہ مسلمان کفار کے قافلوں کو تو بے شک روکتے اور ان کے آدمیوں کو
مارتے لیکن قافلوں کے اموال کو اپنے تصرف میں نہ لاتے بلکہ اپنے خرچ پر اپنی فوج کی حفاظت میں
نہایت احتیاط کے ساتھ مکہ بھجوا دیا کرتے تاکہ ان اموال کی مدد سے قریش دو چار اور جرار لشکر تیار کر کے
مسلمانوں کے خلاف مدینہ پر چڑھا لاتے ؟ اگر ان کا یہی خیال ہے تو انہیں یہ خیال مبارک ہو.ہمیں
اعتراف ہے کہ اسلام کا دامن اس قسم کی بے وقوفی اور بے غیرتی اور خود کشی کی تعلیم سے پاک ہے اور یہ کہنا
کہ ان قافلوں کی روک تھام میں مسلمانوں کو لوٹ مار کی تعلیم دی جاتی تھی کس قدر ظلم ، کس قدر انصاف سے
بعید ہے.کیا اس قوم کو لوٹ مار کی تعلیم دی جاتی تھی جن میں سے بعض نے ایک جہاد کے سفر میں بھوک سے
سخت تنگ آکر اور گویا موت کے منہ پر پہنچ کر کسی کے ایک گلہ میں سے دو چار بکریاں پکڑ کر ذبح کرلیں مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر غصہ میں ہنڈیوں کو الٹ دیا اور گوشت کو مٹی میں مسلتے ہوئے
فرمایا کہ یہ لوٹ کا مال تمہارے لئے کس نے حلال کیا ہے؟ یہ تو ایک مردار سے بڑھ کر نہیں ؟“ پھر کیا اس
قوم کو لوٹ مار کی تعلیم دی جاتی تھی جن میں سے نو مسلم لوگ جہاد پر جاتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے آ آ کر پوچھتے تھے کہ یارسول اللہ! اگرلڑائی میں ایک شخص کی اصل نیت تو حفاظت دین ہو لیکن اسے کچھ
یہ بھی خیال ہو کہ شاید غنیمت کا مال بھی مل جائے گا، تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ہوگا ؟ اور آپ فرماتے
تھے مہرگز نہیں ہرگز نہیں ایسے شخص کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے“ کیا ان واقعات کے ہوتے ہوئے قافلوں
کی روک تھام کو لوٹ مار کی تعلیم سمجھا جاسکتا ہے؟ پھر یہی نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو
سمجھاتے رہتے تھے کہ جہاد میں دنیا کے خیالات کی ملونی نہیں ہونی چاہئے بلکہ صحابہ پر آپ کی اس تعلیم کا
اثر بھی تھا اور یہ اثر اس قدر غالب تھا کہ وہ نہ صرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ان کے دلوں میں دنیا
طلبی کے خیالات جاگزیں نہ ہوں بلکہ بعض اوقات وہ ایسے جائز موقعوں سے بھی بچتے تھے جن میں کمزور
طبیعتوں کے لئے اس قسم کے خیالات پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا تھا.چنانچہ غزوہ بدر کے متعلق روایت
آتی ہے کہ کئی صحابہ اس غزوہ میں اس لئے شریک نہیں ہوئے تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہم صرف قافلہ کی
Page 384
۳۶۹
روک تھام کے لئے اختیار کی جارہی ہے والا اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ قریش کے لشکر کے ساتھ جنگ ہوگا تو وہ
ضرور شامل ہوتے.اور یہ اس بات کا ایک عملی ثبوت ہے کہ صحابہ کو قافلوں کی روک تھام میں ان کے
اموال و امتعہ کی وجہ سے کوئی شغف نہیں تھا.کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صورت حال یہ ہونی چاہئے تھی کہ کسی
قافلہ کی روک تھام کے موقع پر صحابہ زیادہ کثرت کے ساتھ شامل ہونے کے لئے آگے بڑھتے مگر یہاں
معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے.میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے صحابہ ایک جیسے تھے.بیشک ان میں
بعض کمزور بھی تھے اور طبعاً یہ کمزوری ابتداء میں نسبتاً زیادہ تھی مگر جو تبدیلی صحابہ کی جماعت نے آپ کی
تربیت کے ماتحت دکھائی وہ فی الجملہ نہایت محیر العقول اور حقیقتا بے نظیر تھی.ل : ابن ہشام وطبری وا بن سعد
Page 385
٣٧٠
ابتدائی لڑائیاں ، روزہ کی ابتدا، تحویل قبلہ
اور
جنگ بدر کے متعلق ابتدائی بحث
غزوات وسرایا کا آغاز اور غزوہ وڈان صفر ۲ ہجری اب مغازی کا عملی آغاز ہوتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا
کہ کبھی تو خود صحابہ کو ساتھ لے کر نکلتے تھے اور کبھی کسی صحابی کی امارت میں کوئی دستہ روانہ فرماتے تھے.مؤرخین نے ہر دو قسم کی مہموں کو الگ الگ نام دئے ہیں.چنانچہ جس مہم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود
بنفس نفیس شامل ہوئے ہوں اس کا نام مؤرخین غزوہ رکھتے ہیں اور جس میں آپ خود شامل نہ ہوئے ہوں
اس کا نام سریہ یا بعث رکھا جاتا ہے.مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ غزوہ اور سر یہ دونوں میں مخصوص طور پر
جہاد بالسیف کی غرض سے نکلنا ضروری نہیں بلکہ ہر وہ سفر جس میں آپ جنگ کی حالت میں شریک ہوئے
ہوں غزوہ کہلاتا ہے خواہ وہ خصوصیت کے ساتھ لڑنے کی غرض سے نہ کیا گیا ہو اور اسی طرح ہر وہ سفر جو آپ
کے حکم سے کسی جماعت نے کیا ہو مؤرخین کی اصطلاح میں سریہ یا بعث کہلاتا ہے خواہ اس کی غرض وغایت
لڑائی نہ ہو لیکن بعض لوگ ناواقفیت سے ہر غزوہ اور سریہ کو لڑائی کی مہم سمجھنے لگ جاتے ہیں جو درست نہیں.یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جہاد بالسیف کی اجازت ہجرت کے دوسرے سال ماہ صفر میں نازل ہوئی.چونکہ قریش کے خونی ارادوں اور ان کی خطرناک کارروائیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو محفوظ رکھنے
کے لئے فوری کارروائی کی ضرورت تھی اس لئے آپ اسی ماہ میں مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر
اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے.روانگی سے قبل آپ نے اپنے پیچھے مدینہ میں
سعد بن عبادہ رئیس خزرج کو امیر مقرر فرمایا اور مدینہ سے جنوب مغرب کی طرف مکہ کے راستہ پر روانہ ہو گئے
Page 386
۳۷۱
اور بالآخر مقام وڈان تک پہنچے.اس علاقہ میں قبیلہ بنو ضمرہ کے لوگ آباد تھے.یہ قبیلہ بنو کنانہ کی ایک شاخ
تھا اور اس طرح گویا یہ لوگ قریش کے چازاد بھائی تھے.یہاں پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ
بنو ضمرة کے رئیس کے ساتھ بات چیت کی اور باہم رضامندی سے آپس میں ایک معاہدہ ہو گیا.جس کی
شرطیں یہ
تھیں کہ بنو مرۃ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن
کی مدد نہیں کریں گے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمانوں کی مدد کے لئے بلائیں گے، تو وہ
فوراً آجائیں گے.دوسری طرف آپ نے مسلمانوں کی طرف سے یہ عہد کیا کہ مسلمان قبیلہ بنوضمرة کے
ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور بوقت ضرورت ان کی مدد کریں گے.یہ معاہدہ با قاعدہ لکھا
گیا اور فریقین کے اس پر دستخط ہوئے اور پندرہ دن کی غیر حاضری کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
واپس تشریف لے آئے یا غزوہ وڈ ان کا دوسرا نام غزوہ ابوا بھی ہے کیونکہ وڈان کے قریب ہی ابوا کی بستی
بھی ہے اور یہ مقام ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا.مؤرخین لکھتے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوہ میں بن ضمرہ کے ساتھ قریش مکہ کا بھی خیال تھا.اس کا مطلب
یہی ہے کہ دراصل آپ کی یہ مہم قریش کی خطرناک کارروائیوں کے سدباب کے لئے تھی اور اس میں
زہر یلے اور خطرناک اثر کا ازالہ مقصود تھا جو قریش کے قافلے وغیرہ مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں
پیدا کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ان ایام میں بہت نازک ہو رہی تھی.یہ عبيدة بن الحارث ربیع الاول ۲ ہجری غزوہ وڈان سے واپس آنے پر ماہ ربیع الاول کے
شروع میں آپ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار
،
عبيدة بن الحارث مطلبی کی امارت میں ساٹھ شتر سوار مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا.اس مہم کی غرض بھی
قریش مکہ کے حملوں کی پیش بندی تھی.چنانچہ جب عبیدۃ بن الحارث اور ان کے ساتھی کچھ مسافت طے
کر کے ثنية المرة کے پاس پہنچے تو ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کے دوسو مسلح نو جوان عکرمہ بن ابو جہل کی
کمان میں ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں.فریقین ایک دوسرے کے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کے مقابلہ
میں کچھ تیر اندازی بھی ہوئی.لیکن پھر مشرکین کا گروہ یہ خوف کھا کر کہ مسلمانوں کے پیچھے کچھ کمک مخفی ہوگی
ان کے مقابلہ سے پیچھے ہٹ گیا اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا.البتہ مشرکین کے لشکر میں سے دو
شخص مقداد بن عمر و در عتبہ بن غزوان ہعکرمہ بن ابو جہل کی کمان سے خود بخود بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ
ابن ہشام وزرقانی : ابن ہشام وطبری سے : تاریخ الخمیس
Page 387
۳۷۲
آملے اور لکھا ہے کہ وہ اسی غرض سے قریش کے ساتھ نکلے تھے کہ موقع پا کر مسلمانوں میں آملیں یا کیونکہ
وہ دل سے مسلمان تھے مگر بوجہ اپنی کمزوری کے قریش سے ڈرتے ہوئے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور ممکن
ہے کہ اسی واقعہ نے قریش کو بد دل کر دیا ہو اور انہوں نے اسے بد فال سمجھ کر پیچھے ہٹ جانے کا فیصلہ
کر لیا ہو.تاریخ میں یہ مذکور نہیں ہے کہ قریش کا یہ لشکر جو یقیناً کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا اور جس کے متعلق
ابن اسحاق نے جمع عظیم (یعنی ایک بڑا لشکر ) کے الفاظ استعمال کئے ہیں کسی خاص ارادہ سے اس
طرف آیا تھا لیکن یہ یقینی ہے کہ ان کی نیت بخیر نہیں تھی اور یہ خدا کا فضل تھا کہ مسلمانوں کو چوکس پا کر
اور اپنے آدمیوں میں سے بعض کو مسلمانوں کی طرف جاتا دیکھ کر ان کو ہمت نہیں ہوئی اور وہ واپس لوٹ
گئے اور صحابہ کو اس مہم کا یہ عملی فائدہ ہو گیا کہ دو مسلمان روحیں قریش کے ظلم سے نجات پاگئیں.سریہ حمزہ بن عبد المطلب ربیع الاول ۲ ہجری اسی ماہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں
شتر سوار مہاجرین کے ایک اور دستہ کو اپنے حقیقی
چا حمزہ بن عبد المطلب کی سرداری میں مدینہ سے مشرقی جانب سیف البحر علاقہ عیص کی طرف روانہ
فرمایا.حمزہ اور ان کے ساتھی جلدی جلدی وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کارئیس اعظم ابو جہل تین سو
سواروں کا ایک لشکر لئے ان کے استقبال کو موجود ہے.مسلمانوں کی تعداد سے یہ تعداد دس گنے زیادہ تھی
مگر مسلمان خدا اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں گھر سے نکلے تھے اور موت کا ڈرانہیں پیچھے نہیں
ہٹا سکتا تھا.دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل میں صف آرائی کرنے لگ گئیں اور لڑائی شروع ہونے
والی ہی تھی کہ اس علاقہ کے رئیس مجددی بن عمر والجبنی نے جو دونوں فریق کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا
درمیان میں پڑ کر بیچ بچاؤ کرا دیا اور لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی.ابن سعد نے جو عموماً اپنے استاد واقدی
کی اتباع کرتا ہے لکھا ہے کہ یہ قریش کا ایک قافلہ تھا جس سے مسلمانوں کا سامنا ہوا تھا لیکن ابن اسحاق
نے بروایت ابن ہشام قافلہ کا کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ صرف یہ لکھا ہے کہ قریش کے تین سو سواروں سے سامنا
ہوا تھا جو ابوجہل کے زیر کمان تھے اور کفار کی تعداد اور دوسرے قرائن سے ابن اسحاق کی روایت صحیح
ثابت ہوتی ہے اور یہ یقینی ہے کہ کفار کا یہ دستہ مسلمانوں کے خلاف نکلا تھا.چنانچہ کر زبن جابر فہری کا
حملہ بھی جس کا ذکر آگے آتا ہے اس خیال کا مؤید ہے.لے طبری وابن ہشام
ابن ہشام وطبری
Page 388
۳۷۳
غزوہ بواط ربیع الآخر ۲ ہجری اسی مہینہ کے آخری ایام یا ربیع الآخر کے شروع میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو پھر قریش کی طرف سے کوئی خبر موصول ہوئی جس پر آپ
مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر خود مدینہ سے نکلے اور اپنے پیچھے سائب بن عثمان بن مظعون
کو مدینہ کا امیر مقر فرمایا لیکن قریش کا پتہ نہیں چل سکا اور آپ بواط تک پہنچ کر واپس تشریف لے آئے.غزوہ عشیرہ اور سر یہ سعد بن ابی وقاص جمادی الاولی ۲ ہجری اس کے بعد جمادی الاولی میں
پھر قریش مکہ کی طرف سے کوئی
خبر پا کر آپ مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور اپنے پیچھے اپنے رضاعی بھائی ابوسلمہ
بن عبدالاسد کو امیر مقرر فرمایا.اس غزوہ میں آپ کئی چکر کاٹتے ہوئے بالآخر ساحل سمندر کے قریب منع
کے پاس مقام عشیرہ تک پہنچے اور گوقریش کا مقابلہ نہیں ہوا مگر اس میں آپ نے قبیلہ بنومد لج کے ساتھ انہیں
شرائط پر جو بنوضمرہ کے ساتھ قرار پائی تھیں ایک معاہدہ طے فرمایا اور پھر واپس تشریف لے آئے.اسی سفر
کے دوران میں آپ نے سعد بن ابی وقاص کو آٹھ مہاجرین کے ایک دستہ پر امیر مقرر کر کے قریش کی
خبر رسانی کے لئے خراء کی طرف روانہ فرمایا ہے
کرز بن جابر کا حملہ اور غز وہ سفوان جمادی الآخر ۲ ہجری مگر باوجود صحابہ کی اس قدر بیدار
مغزی اور مسلمان پارٹیوں کے مدینہ
کے گردونواح میں اس طرح ہوشیاری کے ساتھ چکر لگاتے رہنے کے قریش کی شرارت نے اپنے لئے
راستہ پیدا کر ہی لیا.چنانچہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے دس دن بھی نہیں
گزرے تھے کہ مکہ کے ایک رئیس کرز بن جابر فہری نے قریش کے ایک دستہ کے ساتھ کمال ہوشیاری سے
مدینہ کی چراگاہ پر جو شہر سے صرف تین میل پر تھی اچانک حملہ کیا اور مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ لوٹ کر چلتا
ہوا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی تو آپ فور ازید بن حارثہ کو اپنے پیچھے امیر مقرر کر کے اور
مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر اس کے تعاقب میں نکلے اور سفوان تک جو بدر کے پاس ایک جگہ
ہے اس کا پیچھا کیا مگر وہ بیچ کر نکل گیا.اس غزوہ کو غزوہ بدرالا ولی بھی کہتے ہیں کے
کرز بن جابر کا یہ حملہ ایک معمولی بدویانہ غارت گری نہیں تھی بلکہ یقینا وہ قریش کی طرف سے مسلمانوں
کے خلاف خاص ارادے سے آیا تھا بلکہ بالکل ممکن ہے کہ اس کی نیت خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
طبری وابن ہشام
ابن ہشام
: ابن ہشام
Page 389
۳۷۴
کی ذات کو نقصان پہنچانے کی ہو، مگر مسلمانوں کو ہوشیار پاکر ان کے اونٹوں پر ہاتھ صاف کرتا ہوا نکل
گیا.اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مدینہ پر چھاپے مار مار کر مسلمانوں
کو تباہ و برباد کیا جاوے.یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ گو اس سے پہلے مسلمانوں کو جہاد بالسیف کی اجازت
ہو چکی تھی اور انہوں نے خود حفاظتی کے خیال سے اس کے متعلق ابتدائی کارروائی بھی شروع کر دی تھی
لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کفار کو عملاً کسی قسم کا مالی یا جانی نقصان نہیں پہنچا تھا لیکن کرز بن جابر کے حملہ
سے مسلمانوں کو عملاً نقصان پہنچا.گویا مسلمانوں کی طرف سے قریش کا چیلنج قبول کر لئے جانے کے بعد
بھی عملی جنگ میں کفار ہی کی پہل رہی.سریہ عبداللہ بن جحش بطرف نخلہ کرز بن جابر کے اچانک حملہ نے طبعا مسلمانوں کو بہت
متوحش کر دیا تھا اور چونکہ رؤساء قریش کی یہ دھمکی پہلے سے
موجود تھی کہ ہم مدینہ پر حملہ آور ہوکر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، مسلمان سخت فکرمند ہوئے اور انہی
خطرات کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ قریش کی حرکات وسکنات کا زیادہ قریب
سے ہو کر علم حاصل کیا جاوے تا کہ ان کے متعلق ہر قسم کی ضروری اطلاع بر وقت میسر ہو جاوے اور مدینہ
ہر قسم کے اچانک حملوں سے محفوظ رہے.چنانچہ اس غرض سے آپ نے آٹھ مہاجرین کی ایک پارٹی تیار
کی یا اور مصلحتاً اس پارٹی میں ایسے آدمیوں کو رکھا جو قریش کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے کے تا کہ
قریش کے مخفی ارادوں کے متعلق خبر حاصل کرنے میں آسانی ہو اور اس پارٹی پر آپ نے اپنے پھوپھی زاد
بھائی عبداللہ بن جحش کو امیر مقررفرمایا.اور اس خیال سے کہ اس پارٹی کی غرض و غایت عامتہ المسلمین سے
بھی مخفی رہے آپ نے اس سریہ کو روانہ کرتے ہوئے اس سریہ کے امیر کو بھی یہ نہیں بتایا کہ تمہیں کہاں
اور کس غرض سے بھیجا جارہا ہے بلکہ چلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک سر بمہر خط دے دیا اور فرمایا کہ اس
خط میں تمہارے لئے ہدایات درج ہیں.جب تم مدینہ سے دو دن کا سفر طے کر لو تو پھر اس خط کو کھول کر اس
کی ہدایات کے مطابق عمل درآمد کرنا.چنانچہ عبد اللہ اور ان کے ساتھی اپنے آقا کے حکم کے ماتحت روانہ
ہو گئے اور جب دودن کا سفر طے کر چکے تو عبد اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کھول کر دیکھا
تو اس میں یہ الفاظ درج تھے.اِمُضِ حَتَّى تُنْزِلَ نَحْلَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرُصِدُ بِهَا قُرَيْشًا
وَتَعْلَمُ لَنَا مِنْ اَخْبَارِهِمْ - یعنی " تم مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلہ میں جاؤ اور وہاں جا کر قریش
ل ابن ہشام وطبری
واقدی
: طبری وسیرۃ ابن ہشام
Page 390
۳۷۵
کے حالات کا علم لو اور پھر ہمیں اطلاع لا کر دو.“ اور چونکہ مکہ سے اس قدر قریب ہو کر خبر رسانی کرنے کا
کام بڑا نازک تھا.آپ نے خط کے نیچے یہ ہدایت بھی لکھی تھی کہ اس مشن کے معلوم ہونے کے بعد
اگر تمہارا کوئی ساتھی اس پارٹی میں شامل رہنے سے متامل ہو اور واپس چلا آنا چا ہے تو اسے واپس آنے کی
اجازت دے دو.عبداللہ نے آپ کی یہ ہدایت اپنے ساتھیوں کو سنا دی اور سب نے یک زبان ہوکر کہا
کہ ہم بخوشی اس خدمت کے لئے حاضر ہیں.اس کے بعد یہ جماعت نخلہ کی طرف روانہ ہوئی.راستہ میں
سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ کھویا گیا اور وہ اس کی تلاش کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے
بچھڑ گئے اور باوجود بہت تلاش کے انہیں نہ مل سکے اور اب یہ پارٹی صرف چھ کس کی رہ گئی.مسٹر مار گولیس
اس موقع پر لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور عتبہ نے جان بوجھ کر اپنا اونٹ چھوڑ دیا تھا اور اس بہانہ سے
پیچھے رہ گئے.ان جاں نثاران اسلام پر جن کی زندگی کا ایک ایک واقعہ ان کی شجاعت اور فدائیت پر شاہد
ہے اور جن میں سے ایک غزوہ بئر معونہ میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوا اور دوسرا کئی خطرناک معرکوں میں
نمایاں حصہ لے کر بالآخر عراق کا فاتح بنا اس قسم کا شبہ کرنا اور شبہ بھی محض اپنے من گھڑت خیالات کی بناء پر
کرنا مسٹر مارگولیس ہی کا حصہ ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ مارگولیس صاحب اپنی کتاب میں دعوئی یہ کرتے
ہیں کہ میں نے یہ کتاب ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر لکھی ہے.خیر یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا.مسلمانوں
کی یہ چھوٹی سی جماعت نخلہ پہنچی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور ان میں سے بعض نے اخفاء راز کے
خیال سے اپنے سر کے بال منڈوادے تاکہ را بگیر وغیرہ ان کو عمرہ کے خیال سے آئے ہوئے لوگ سمجھ کر کسی
قسم کا شبہ نہ کریں لیکن ابھی ان کو وہاں پہنچے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اچانک وہاں قریش کا ایک چھوٹا سا
قافلہ بھی آن پہنچا جو طائف سے مکہ کی طرف جارہا تھا اور ہر دو جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے
ہوگئیں.مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
خفیہ خفیہ خبر رسانی کے لئے بھیجا تھا، لیکن دوسری طرف قریش سے جنگ شروع ہو چکی تھی اور اب دونوں
حریف ایک دوسرے کے سامنے تھے اور پھر طبعا یہ اندیشہ بھی تھا کہ اب جو قریش کے ان قافلہ والوں نے
مسلمانوں کو دیکھ لیا ہے تو اس خبر رسانی کا راز بھی مخفی نہ رہ سکے گا.ایک دقت یہ بھی تھی کہ بعض مسلمانوں کو
خیال تھا کہ شاید یہ دن رجب یعنی شہر حرام کا آخری ہے جس میں عرب کے قدیم دستور کے مطابق لڑائی
نہیں ہونی چاہئے تھی.اور بعض سمجھتے تھے کہ رجب گزر چکا ہے اور شعبان شروع ہے.اور بعض روایات
: طبری وابن ہشام
ابن ہشام وطبری
Page 391
میں ہے کہ یہ سر یہ جمادی الآخر میں بھیجا گیا تھا اور شک یہ تھا کہ یہ دن جمادی کا ہے یار جب کا.لیکن
دوسری طرف نخلہ کی وادی عین حرم کے علاقہ کی حد پر واقع تھی اور یہ ظاہر تھا کہ اگر آج ہی کوئی فیصلہ نہ ہوا تو
کل کو یہ قافلہ حرم کے علاقہ میں داخل ہو جائے گا جس کی حرمت یقینی ہوگی.غرض ان سب باتوں کو
سوچ کر مسلمانوں نے آخر یہی فیصلہ کیا کہ قافلہ پر حملہ کر کے یا تو قافلہ والوں کو قید کر لیا جاوے
اور یا مار دیا جاوے.چنانچہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر حملہ کر دیا جس کے نتیجہ میں کفار کا ایک آدمی جس کا
نام عمرو بن الحضر می تھا مارا گیا اور دو آدمی قید ہو گئے ، لیکن بدقسمتی سے چوتھا آدمی بھاگ کرنکل
گیا اور مسلمان اسے پکڑ نہ سکے اور اس طرح ان کی تجویز کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئی.اس کے بعد
مسلمانوں نے قافلہ کے سامان پر قبضہ کر لیا اور چونکہ قریش کا ایک آدمی بچ کر نکل گیا تھا اور یقین تھا کہ
اس لڑائی کی خبر جلدی مکہ پہنچ جائے گی عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی سامان غنیمت لے کر جلد جلد
مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے.مسٹر مار گولیس اس موقع پر لکھتے ہیں کہ دراصل محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ دستہ دیدہ دانستہ اس نیت
سے شہر حرام میں بھیجا تھا کہ چونکہ اس مہینہ میں قریش طبعا غافل ہوں گے.مسلمانوں کو ان کے قافلہ کے
لوٹنے کا آسان اور یقینی موقع مل جائے گا لیکن ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مختصر پارٹی کو اتنے دور دراز
علاقہ میں کسی قافلہ کی غارت گری کے لئے نہیں بھیجا جا سکتا خصوصاً جبکہ دشمن کا ہیڈ کوارٹر اتنا قریب ہو اور
پھر یہ بات تاریخ سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ پارٹی محض خبر رسانی کی غرض سے بھیجی گئی تھی اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا کہ صحابہ نے قافلہ پر حملہ کیا تھا تو آپ سخت ناراض ہوئے.چنانچہ
روایت ہے کہ جب یہ جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو سارے
ماجرا کی اطلاع ہوئی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا مَا اَمَرْتُكُمْ بِقِتَالٍ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ -
میں نے تمہیں شہر حرام میں لڑنے کی اجازت نہیں دی ہوئی.وَأَبِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا -
اور آپ نے مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا.اس پر عبداللہ اور ان کے ساتھی سخت نادم اور پشیمان
ہوئے.وَظَنُّوا أَنَّهُمُ قَدْ هَلَكُوا.اور انہوں نے خیال کیا کہ بس اب ہم خدا اور اس کے رسول کی
ناراضگی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے.صحابہ نے بھی ان کو سخت ملامت کی اور کہا صَنَعْتُمُ مَالَمْ تُؤْمَرُوا
زرقانی
: طبری وسیرۃ ابن ہشام
: طبری وابن ہشام
: طبری و سیرۃ ابن ہشام
Page 392
۳۷۷
وَقَاتَلْتُمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِقِتَالِ ا یعنی ” تم نے وہ کام کیا جس کا تم کوحکم نہیں دیا گیا
تھا اور تم نے شہر حرام میں لڑائی کی حالانکہ اس مہم میں تو تم کو مطلقاً لڑائی کا حکم نہیں تھا.“ دوسری طرف
قریش نے بھی شور مچایا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کو توڑ دیا ہے اور چونکہ جوشخص مارا گیا تھا یعنی
عمرو بن الحضر می وہ ایک رئیس آدمی تھا اور پھر وہ عقبہ بن ربیعہ رئیس مکہ کا حلیف بھی تھا اس لئے بھی اس
واقعہ نے قریش کی آتش غضب کو بہت بھڑکا دیا اور انہوں نے آگے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ
مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی.چنانچہ جنگ بدر جس کا ذکر آگے آتا ہے زیادہ ترقریش کی اسی
تیاری اور جوش عداوت کا نتیجہ تھا.الغرض اس واقعہ پر م
پر مسلمانوں اور کفار ہر دو میں بہت چہ میگوئی ہوئی اور
بالآخر ذیل کی قرآنی وحی نازل ہو کر مسلمانوں کی تشفی کا موجب ہوئی.يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالُ فِيْهِ كَبِيرٌ وَصَلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ
*
أكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ
عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا " یعنی "لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ تو ان کو
جواب دے کہ بے شک شہر حرام میں لڑنا بہت بری بات ہے لیکن شہر حرام میں خدا کے دین سے لوگوں کو
جبر ارو کنا بلکہ شہر حرام اور مسجد حرام دونوں کا کفر کرنا یعنی ان کی حرمت کو توڑنا اور پھر حرم کے علاقہ سے اس
کے رہنے والوں کو بزور نکالنا جیسا کہ اے مشرکو تم لوگ کر رہے ہو یہ سب باتیں خدا کے نزدیک شہر حرام
میں لڑنے کی نسبت بھی زیادہ بری ہیں اور یقیناً شہر حرام میں ملک کے اند رفتنہ پیدا کرنا اس قتل سے بدتر ہے
جو فتنہ کو روکنے لے لئے کیا جاوے.اور اے مسلمانو! کفار کا تو یہ حال ہے کہ وہ تمہاری عداوت میں اتنے
اندھے ہورہے ہیں کہ کسی وقت اور کسی جگہ بھی وہ تمہارے ساتھ لڑنے سے باز نہیں آئیں گے اور وہ اپنی یہ
لڑائی جاری رکھیں گے حتی کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں بشرطیکہ وہ اس کی طاقت پائیں.چنانچہ
تاریخ سے ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف رؤسائے قریش اپنے خونی پراپیگنڈا کو اشہر حرام میں بھی برابر
جاری رکھتے تھے بلکہ اشہر حرم کے اجتماعوں اور سفروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان مہینوں میں اپنی
مفسدانہ کارروائیوں میں اور بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے اور پھر کمال بے حیائی سے اپنے دل کو جھوٹی تسلی
دینے کے لئے وہ عزت کے مہینوں کو اپنی جگہ سے ادھر ادھر منتقل بھی کر دیا کرتے تھے جسے وہ نسئی کے نام
سے پکارتے تھے اور پھر آگے چل کر تو انہوں نے غضب ہی کر دیا کہ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں باوجود پختہ
طبری
: سورة بقره : ۲۱۸
Page 393
۳۷۸
عہد و پیمان کے کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں نے حرم کے علاقہ میں مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ کے
خلاف تلوار چلائی اور پھر جب مسلمان اس قبیلہ کی حمایت میں نکلے تو ان کے خلاف بھی عین حرم میں تلوار
استعمال کی.پس اس جواب سے مسلمانوں کی تو تسلی ہونی ہی تھی قریش بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے اور اس
دوران میں ان کے آدمی بھی اپنے دو قیدیوں کو چھڑوانے کے لئے مدینہ پہنچ گئے لیکن چونکہ ابھی تک سعد بن
ابی وقاص اور عقبہ واپس نہیں آئے تھے.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق سخت خدشہ تھا کہ
اگر وہ قریش کے ہاتھ پڑ گئے تو قریش انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے.اس لئے آپ نے ان کی واپسی تک
قیدیوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے آدمی بخیریت مدینہ پہنچ جائیں گے تو پھر میں تمہارے
آدمیوں کو چھوڑ دوں گا.چنانچہ جب وہ دونوں واپس پہنچ گئے تو آپ نے فدیہ لے کر دونوں قیدیوں کو
چھوڑ دیا لیکن ان قیدیوں میں سے ایک شخص پر مدینہ کے قیام کے دوران میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے اخلاق فاضلہ اور اسلامی تعلیم کی صداقت کا اس قدر گہرا اثر ہو چکا تھا کہ اس نے آزاد ہو کر بھی واپس
جانے سے انکار کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ بگوشوں میں
شامل ہو گیا اور بالآخر بئر معونہ میں شہید ہوا.اس کا نام حکم بن کیان تھا لے
تحویل قبلہ باوجود جنگ وجدال کی بے انتہا مصروفیت کے تکمیل و تاسیس مذہب کا کام نہیں رک سکتا
تھا کیونکہ بعثت نبوی کی یہی علت اولی تھی.پنجگانہ نماز مکہ میں ہی شروع ہو چکی تھی.مدینہ میں باجماعت نماز کے التزام نے اذان کی ضرورت محسوس کرائی اور اس کا انتظام کیا گیا.مگر
مسلمانوں
کا قبلہ ابھی تک بیت المقدس تھا اور مکہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور مدینہ کے ابتدائی زمانہ میں بھی یہی طریق جاری
رہا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں
کا قبلہ مکہ کے کعبہ کو قرار دیا
جاوے، کیونکہ وہ خدا کی عبادت کا پہلا گھر تھا جو دنیا میں تعمیر ہوا اور ابوالانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ
اور عربوں کے جد اعظم اسماعیل ذبیح اللہ کی یادگار بھی اسی گھر سے وابستہ تھی اور پھر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا مولد ومسکن اور اسلام کا مبدا و منبع ہونے کی حیثیت میں بھی کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ بننے کا
حق دار تھا لیکن چونکہ ابھی تک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے آپ
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور یہ سلسلہ ہجرت کے سولہ سترہ ماہ بعد تک جاری رہا
طبری
Page 394
۳۷۹
لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو ان کے اصل قبلہ پر قائم کر دیا جاوے.چنانچہ ہجرت کے
دوسرے سال شعبان کے مہینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حکم الہی کے نزول کی محرک ہوئی
اور یکلخت مسلمانوں کا رخ بیت المقدس کی طرف سے کعبہ کی طرف پھر گیا.قرآن شریف میں جو آیات
اس بارہ میں نازل ہوئیں.وہ یہ ہیں.سَيَقُولُ السُّنَهَاءِ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ
الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) قَدْنَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ
قِبْلَةً تَرْضُهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلَّوْا وَجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ.وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُوْنُوْايَاتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
ضرور بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے کس بات نے
پھیر دیا جس پر کہ وہ تھے.تو کہہ دے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لئے ہے وہ جسے چاہتا ہے
صراط مستقیم کی طرف راستہ دکھا دیتا ہے اور اے رسول! ہم نے تیرے پہلے قبلہ کو تو صرف اس
امتحان کے طور پر رکھا تھا کہ یہ ظاہر ہو جاوے کہ کون خدا کے رسول کی سچی اتباع اختیار کرتا ہے
اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور بے شک پہلا قبلہ طبائع پر ایک بوجھ رہا ہے سوائے
ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور اے رسول! ہم دیکھتے ہیں کہ تیری توجہ
قبلہ کے معاملہ میں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہے کہ کب کعبتہ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم اترتا
ہے.لہذا اب ہم پھیر دیتے ہیں تجھے اس قبلہ کی طرف جو تجھے پسند ہے.پس اے رسول اپنے
رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لے اور اے مسلمانو! جہاں کہیں بھی تم ہوا پنا رخ مسجد حرام کی
طرف رکھا کرو اور جانو کہ ہر قوم کے لئے توجہ کی ایک خاص سمت ہوتی ہے اور گو ہم نے تمہاری
ظاہری سمت کعبہ کو مقررکیا ہے لیکن یاد رکھو تمہاری باطنی سمت نیکیوں کی طرف بڑھنا ہونی چاہئے
: سورة البقره : ۱۴۳ تا ۱۴۵
: سورة البقره :
۱۴۹ :
Page 395
۳۸۰
اور اس ظاہر وباطن کی پجہتی سے یہ فائدہ ہوگا کہ تم خواہ دنیا کے کسی حصہ میں پھیلے ہوئے ہو گے تم
میں اتحادر ہے گا.بے شک
اللہ جو چاہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے.“
ان آیات قرآنی میں جہاں تحویل قبلہ کا حکم ہے وہاں قبلہ کی حکمت اور ضرورت بھی بیان کی گئی ہے کہ
اس سے قوم میں ظاہری بیجہتی اور اتحاد فی الصورت قائم رہتے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شروع شروع
میں اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ تک مسلمانوں کو بیت المقدس کے قبلہ پر اس مصلحت سے قائم رکھا تھا کہ وہ
مشرکین عرب کے لئے جن کی ساری توجہ کا مرکز کعبہ تھا بطور ایک امتحان کے رہے اور وہ اپنے اندر ایمان
کی خاطر قربانی کرنے کی روح پیدا کریں، لیکن جب آزمائش کا مناسب زمانہ گزر گیا تو اصل قبلہ کی طرف
رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا.اس موقع پر سرولیم میور نے اعتراض کیا ہے کہ شروع شروع میں مسلمان
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اس لئے نماز پڑھتے تھے تا کہ اس طرح مدینہ کے یہودیوں کو اپنی طرف
مائل کریں ، لیکن جب دیکھا کہ وہ اس داؤ میں نہیں آتے تو رخ بدل کر کعبہ کی طرف کر لیا گیا تا کہ مشرکین
عرب کو خوش کرنے کی کوشش کی جاوے.تعصب بے شک انسان کو اندھا کر دیتا ہے لیکن اگر سرولیم
جیسا قابل شخص جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوبے کا کامیاب حاکم رہ چکا ہے اسلام کے متعلق ایسی
بے بنیاد باتیں کرے تو جائے تعجب ضرور ہے، مگر حقیقت ایسی واضح ہے کہ کسی کے چھپائے چھپ نہیں
سکتی.جو طریق عمل ہجرت سے کئی سال پہلے مکہ میں جاری ہوا ہو اور مدینہ جانے پر چند ماہ کے بعد منسوخ
کر دیا ہو اس کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہود مدینہ کو خوش کرنے کے لئے جاری کیا گیا تھا اور اس کی منسوخی
کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مشرکین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وقوع میں آئی تھی کسی عقل مند کو دھو کے
میں نہیں ڈال سکتا.حقیقت یہ ہے کہ پہلا قبلہ مشرکین کے لئے بطور ایک امتحان کے تھا اور اس امتحان
کا وقت ہجرت سے پہلے ہی مناسب تھا لیکن چونکہ مدینہ میں بھی مشرکین بستے تھے اس لئے مدینہ کے
ابتدائی ایام میں بھی وہ امتحان جاری رہا.مگر جب مشرکین مدینہ قریباً مفقود ہو گئے تو اس امتحان کی ضرورت
نہ رہی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا اور اس حکم میں دو مصلحتیں تھیں.ایک یہ کہ مسلمان اپنے اصل قبلہ
پر قائم ہو گئے اور دوسرے یہ کہ نیا قبلہ یہود کے لئے ایک امتحان بن گیا جیسا کہ پہلا قبلہ مشرکین کے لئے
امتحان تھا.پس حقیقت وہ نہیں جو میور صاحب کے خامہ تعصب نے خلق کی ہے بلکہ اس کے بالکل برعکس
ہے اور قرآن جس کی شہادت کی تاریخی حیثیت کو میور صاحب نے سب شہادتوں سے بڑھ کر قرار دیا ہے
اس کا شاہد ہے.
Page 396
۳۸۱
نماز سے اتر کر اسلامی عبادات کا دوسرا بڑا رکن روزہ ہے.دراصل اسلام نے مختلف قسم
صیام رمضان
کی عبادات مختلف قسم کے تزکیۂ نفس کو مد نظر رکھ کر شروع کی ہیں.یعنی اگر نماز ایک رنگ
میں انسان کی آلائشوں اور کمزوریوں کو دور کرتی ہے اور اسے خدا کا مقرب بننے کے قابل بناتی ہے تو
روزے کسی دوسرے رنگ میں یہ کام سرانجام دیتے ہیں اور زکوۃ ایک تیسرے میدان کے لئے مقرر ہے
اور حج ان تینوں کے علاوہ ایک چوتھا مقصد ہے اور اس طرح مختلف عبادتیں مختلف مقاصد کو پورا کرتی ہیں
اور مختلف جہات سے انسان کی اصلاح اور ترقی کے کام میں محمد ہوتی ہیں اور اگر غور کیا جاوے تو یہ صاف
معلوم ہوتا ہے کہ جس ترتیب سے اسلامی عبادات کے مختلف ارکان شروع ہوئے ہیں وہی ان کی اہمیت کی
ترتیب بھی ہے.یعنی سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ وسیع طور پر انسانی اخلاق اور روحانیت پر اثر
ڈالنے والی عبادت وہ ہے جو سب سے پہلے قائم کی گئی اور اس کے بعد اس سے کم درجہ کی قائم کی گئی اور اس
کے بعد اس سے کم کی وعلی ھذا القیاس.اور جو لوگ عبادات کو محض ایک رسم کے طور پر ادا نہیں کرتے اور ان
کے اثر کو اپنے نفوس میں مطالعہ کرنے کے عادی ہیں وہ یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ عبادات
میں اول
نمبر نماز کا ہے اور پھر اس سے اتر کر روزہ کا.اور پھر دوسری عبادات کا.بہر حال اس وقت تک
صرف نماز مشروع ہوئی تھی اور اب ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی آمد پر روزوں کا بھی آغاز ہوا.یعنی یہ حکم نازل ہوا کہ رمضان کے مہینہ میں تمام بالغ مسلمان مرد و عورت باستثنا بیماروں اور نا توانوں کے
اور باستثنا مسافروں کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے پینے سے پر ہیز کریں
اوران اوقات میں خاوند بیوی کے مخصوص تعلقات سے بھی پرہیز کیا جاوے اور روزوں کے ایام
کو خصوصیت کے ساتھ ذکر الہی اور قرآن خوانی اور صدقہ و خیرات میں گزارا جاوے اور روزوں کی راتوں
میں مخصوص طور پر نماز تہجد کا التزام کیا جاوے وغیر ذالک.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا
ہے کہ آپ کا رمضان گویا ایک مجسم عبادت کا رنگ رکھتا تھا اور گولیوں تو آپ کی ساری زندگی ہی عبادت
تھی ، مگر روزوں میں آپ خصوصیت سے بیشتر حصہ وقت کا نوافل اور ذکر الہی میں گزارتے تھے اور راتوں
کو کثرت کے ساتھ جاگتے تھے اور رمضان میں آپ اتنا صدقہ و خیرات کرتے تھے کہ صحابہ نے اس کو ایک
تیز ہوا کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کسی روک کو خیال میں نہ لائے.نیز روزہ کی روح کو زندہ رکھنے کے لئے
آپ ہمیشہ صحابہ کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ سمجھو کہ بس کھانا پینا چھوڑنے کی رسم ادا کر کے تم خدا کے
قرآن شریف سورۃ بقره و بخاری ابواب الصيام
طبری
بخاری
Page 397
۳۸۲
نز د یک روزہ دار شمار ہو جاؤ گے بلکہ تمہیں روزہ کی اصل روح کوملحوظ رکھنا چاہئے تا کہ اس سے تمہارے اندر
طہارت نفس اور ضبط خواہشات اور مادہ قربانی اور غرباء کی امداد کا احساس پیدا ہواور فرماتے تھے کہ وہ شخص
بہت بد قسمت ہے جس کو کوئی رمضان میسر آئے اور پھر اس کے گزشتہ گناہ معاف نہ ہوں.آپ نوافل کے
طور پر بھی روزہ کی تحریک فرمایا کرتے تھے مگر آپ کی یہ سنت تھی کہ آپ ہر بات میں میانہ روی کا حکم دیتے
تھے.چنانچہ آپ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ کوئی شخص مسلسل روزے رکھتا چلا جاوے اور فرماتے تھے
کہ انسان پر خدا نے اس کے نفس کا بھی حق رکھا ہے اور اس کی بیوی کا بھی حق رکھا ہے اور اس کے بچوں کا
بھی حق رکھا ہے اور اس کے دوستوں کا بھی حق رکھا ہے اور ہمسایوں کا بھی حق رکھا ہے اور اسی طرح
دوسرے حقوق ہیں اور ان میں سے ہر حق کو خدا کی شریعت اور منشا کے ماتحت ادا کرنا عبادت میں داخل
ہے.پس ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ کوئی شخص ایک خاص عبادت پر زور دے کر دوسرے حقوق کو نظر انداز
کر دے.غرض اس طرح اس سال رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور اسلامی عبادات میں
دوسرے رکن کا اضافہ ہوا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح پنجگانہ نماز فرض ہونے سے قبل بھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رنگ میں نفلی نماز پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرماتے
تھے.اسی طرح رمضان کے روزے فرض کئے جانے سے پہلے آپ نفلی روزے بھی رکھتے تھے ،مگر وہ
اس طرح با قاعدہ اور معتین اور موقت صورت میں مشروع نہیں ہوئے تھے.چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ
رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل آپ یوم عاشورہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے
اور صحابہ کو بھی اس کی تحریک فرماتے تھے.رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد رمضان کا آخر آیا تو آپ نے خدا سے حکم پا کر
صدقۃ الفطر کا حکم جاری فرمایا کہ ہر مسلمان جسے اس کی طاقت ہو اپنی طرف سے اور اپنے
اہل و عیال اور توابع کی طرف سے فی کس ایک صاع کے حساب سے کھجور یا انگور یا جو یا گندم وغیرہ
بطور صدقہ عید سے پہلے ادا کرے اور یہ صدقہ غرباء اور مساکین اور یتامیٰ اور بیوگان وغیرہ میں تقسیم کر دیا
جاوے تا کہ ذی استطاعت لوگوں کی طرف سے عبادت صوم کی کمزوریوں کا کفارہ ہو جاوے اور غرباء کے
لئے عید کے موقع پر ایک امداد کی صورت نکل آئے.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر عید
رمضان سے پہلے صدقۃ الفطر باقاعدہ طور پر ہر چھوٹے بڑے مرد عورت مسلمان سے وصول کیا جاتا تھا
عیدالفطر
: ایک عربی پیمانہ ہے جو وزن کے لحاظ سے کچھ اوپر تین سیر گندم کے برابر ہوتا ہے.
Page 398
٣٨٣
اور یتامیٰ اور غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا.عید الفطر بھی اسی سال شروع ہوئی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رمضان کا مہینہ ختم
ہو جانے پر شوال کی پہلی تاریخ کو مسلمان عید منایا کریں.یہ عید اس بات کی خوشی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں رمضان کی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے.مگر کیا شان دلر بائی ہے کہ آپ نے اس خوشی
کے اظہار کے لئے بھی ایک عبادت ہی مقرر فرمائی.چنانچہ حکم دیا کہ عید کے دن تمام مسلمان کسی کھلی جگہ جمع
ہو کر پہلے دو رکعت نماز ادا کیا کریں اور پھر اس نماز کے بعد بے شک جائز طور پر ظاہری خوشی بھی منائیں
کیونکہ روح کی خوشی کے وقت جسم کا بھی حق ہے کہ وہ خوشی میں حصہ لے.دراصل اسلام نے ان تمام بڑی
بڑی عبادتوں کے اختتام پر جو اجتماعی طور پرادا کی جاتی ہیں عیدیں رکھی ہیں.چنانچہ نمازوں کی عید جمعہ ہے
جو گویا ہر ہفتہ کی نمازوں کے بعد آتا ہے اور جسے اسلام میں ساری عیدوں سے افضل قرار دیا گیا ہے
پھر روزوں کی عید عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد آتی ہے.اور حج کی عید عیدالاضحیٰ ہے جو حج کے دوسرے
دن منائی جاتی ہے اور یہ ساری عیدیں پھر خود اپنے اندر ایک عبادت ہیں.الغرض اسلام کی عید میں اپنے
اندر ایک عجیب شان رکھتی ہیں اور ان سے اسلام کی حقیقت پر بڑی روشنی پڑتی ہے اور یہ اندازہ کرنے کا
موقع ملتا ہے کہ کس طرح اسلام مسلمانوں کے ہر کام کو ذکر الہی کے ساتھ پیوند کرنا چاہتا ہے.مجھے تاریخ
سے ہٹنا پڑتا ہے ، ورنہ میں بتاتا کہ کس طرح اسلام نے ایک مسلمان کی ہر حرکت و سکون اور ہر قول و فعل کو
خدا کی یاد کا خمیر دیا ہے.حتی کہ روزمرہ کے معمولی اٹھنے بیٹھنے ، چلنے پھرنے سونے جاگنے ، کھانے
پینے ، نہانے دھونے ، کپڑے بدلنے، جوتا پہننے، گھر سے باہر جانے، گھر کے اندر آنے ،سفر پر جانے ،سفر سے
واپس آنے ، کوئی چیز بیچنے، کوئی چیز خریدنے ، بلندی پر چڑھنے ، بلندی سے اتر نے مسجد میں داخل ہونے ،
مسجد سے باہر آنے ، دوست سے ملنے، دشمن کے سامنے ہونے ، نیا چاند دیکھنے، بیوی کے پاس جانے غرض
ہر کام کے شروع کرنے اور ختم کرنے حتی کہ چھینک اور اباسی تک لینے کو کسی نہ کسی طرح خدا کے ذکر
کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے.اس حالت میں اگر مشرکین عرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو
دراصل اس تعلیم کے لانے والے لیکن کفار کے خیال میں اس تعلیم کے بنانے والے تھے یہ کہتے ہوں کہ
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خدا کا جنون ہو گیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں.واقعی ایک دنیا دار کو یہ باتیں جنون کے
سوا اور کچھ نظر نہیں آسکتیں مگر جس نے اپنی ہستی کی حقیقت کو سمجھا ہے وہ جانتا ہے کہ زندگی اسی کا نام ہے.ل : یہ امور کتب حدیث کے ذریعہ سے اسلامی شریعت میں شائع و متعارف ہیں کسی خاص حوالہ کی ضرورت نہیں.
Page 399
۳۸۴
جنگ بدر کے متعلق ایک ابتدائی بحث اسی سال رمضان کے مہینہ میں بدر کی جنگ وقوع میں
آئی.یہ جنگ چونکہ کئی لحاظ سے تاریخ اسلام کا ایک
نہایت اہم واقعہ ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اس کے متعلق کسی قدر زیادہ تفصیلی نظر ڈالی جاوے.بدر وہ
پہلی باقاعدہ لڑائی ہے جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی اور اس کے اثرات بھی ہر دو فریق کے لئے
نہایت وسیع اور گہرے ثابت ہوئے.یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے اس کا نام ” یوم الفرقان ، یعنی حق
و باطل کے درمیان فیصلہ کا دن رکھا ہے اور اس کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کی خبر رسول
خدا کے ذریعہ قریش مکہ کو ہجرت سے پہلے دی گئی تھی.جنگ بدر کے تحریکی سبب کے متعلق زمانہ حال میں
بعض محققین نے اختلاف کیا ہے اور اسی اختلاف کے متعلق ہم اس ابتدائی نوٹ میں کچھ بحث کرنا چاہتے
ہیں.عام مؤرخین کا یہ خیال ہے اور متقدمین میں سے تو اس بارہ میں کسی ایک مورخ نے بھی اختلاف نہیں
کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ایک تجارتی قافلہ کی اطلاع ملی تھی جو ابوسفیان کی سرداری میں
شام کی طرف سے مکہ کو واپس آرہا تھا اور آپ اسی قافلہ کی روک تھام کے لئے مدینہ سے نکلے تھے لیکن
جب آپ بدر کے قریب پہنچے تو اس وقت آپ کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بڑ الشکر مکہ سے آیا ہے اور پھر
قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور قریش کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مٹھ بھیڑ ہوگئی.دوسری طرف زمانہ حال میں
جماعت احمدیہ قادیان کے ایک معزز فرد مولوی شیر علی صاحب بی.اے نے رسالہ ریویو آف ریلیجنز
قادیان بابت سال ۱۹۱۰ء میں اور ہندوستان کے مشہور مؤرخ مولانا شبلی نعمانی نے سیرۃ النبی میں بعض
قرآنی آیات اور دیگر شہادات سے استدلال کر کے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ میں ہی قریش
کے لشکر کی اطلاع مل گئی تھی اور وہ مدینہ سے ہی لشکر کے مقابلہ کے خیال سے نکلے تھے اور قافلہ کے ارادے
سے نکلنے کا خیال غلط ہے.چنانچہ مولانا شبلی اپنی رائے کا خلاصہ یہ لکھتے ہیں کہ
مدینہ میں یہ مشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آرہے ہیں.آنحضرت
66
صلی اللہ علیہ وسلم نے مدافعت کا قصد کیا اور بدر کا معرکہ پیش آیا.جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خلق اور مسلمانوں کے قومی اخلاق پر روشنی پڑنے
کا سوال ہے یہ اختلاف چنداں اہمیت نہیں رکھتا.صحابہ قافلہ کی روک تھام کے لئے نکلے تھے یا لشکر قریش
کے مقابلہ کی غرض سے یا یہ کہ انہیں دونوں کی اطلاع اور دونوں کا خیال تھا ان میں سے کوئی بھی مقصد ہو وہ
ل : سیرۃ النبی جلد اصفحه ۳۱۸
Page 400
۳۸۵
مقصد جیسا کہ ہم جہاد کی اصولی بحث میں ثابت کر چکے ہیں بالکل درست اور جائز تھا اور کوئی معقول
اور غیر متعصب شخص اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن تاریخی اور علمی نکتہ نگاہ سے یہ اختلاف ایک دلچسپ
بحث کا رنگ اختیار کر گیا ہے اور کوئی علم دوست مورخ اس کی طرف سے بے تو جہی نہیں برت سکتا
اور پھر صحت واقعات کی تحقیق کی ذمہ داری مزید برآں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کی پوری پوری بحث
اور مکمل چھان بین کے لئے ایک طویل مقالہ کی ضرورت ہے جس کی گنجائش ایک خالص تاریخ کی کتاب
میں نہیں نکالی جاسکتی اور حق یہ ہے کہ میں نے اس بحث میں ایک مفصل مضمون لکھا بھی تھا، لیکن پھر اسے اس
خیال سے خارج کر دیا کہ اس قسم کا مضمون حقیقتا علم کلام میں داخل ہے اور عام تاریخ کا حصہ نہیں بننا چاہئے.سواب میں نہایت مختصر طور پر اس معاملہ میں اپنی تحقیق کا ذکر کر کے اصل مضمون کی طرف لوٹتا ہوں.میں نے ہر دو قسم کے خیالات کے متعلق کافی غور کیا ہے لیکن جہاں میں مولوی شیر علی صاحب اور مولانا
شبلی کی تحقیق کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں وہاں میں افسوس کے ساتھ بعض باتوں میں ان بزرگوں سے
اختلاف بھی رکھتا ہوں اور میری رائے میں اصل حقیقت ان ہر دو قسم کے خیالات کے بین بین ہے.یعنی
میری تحقیق یہ ہے کہ ایک طرف تو جدید تحقیق کا یہ حصہ ٹھیک ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہی
لشکر قریش کی آمد کی اطلاع ہو گئی تھی اور دوسری طرف عام مؤرخین کا یہ خیال بھی ہرگز غلط نہیں ہے کہ
صحابہ ( یعنی اکثر صحابہ جیسا کہ ابھی ظاہر ہو جائے گا ) صرف قافلہ ہی کی روک تھام کے خیال سے نکلے تھے
اور لشکر قریش کا علم انہیں بدر کے قریب پہنچ کر ہوا تھا اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے قرآن شریف اور
تاریخ و حدیث دونوں میرے اس خیال کے مؤید ہیں.دراصل ہمارے ان جدید محققین نے قرآن شریف
کے سارے بیان کو اپنے مدنظر نہیں رکھا اور صرف اس کے ایک حصہ کو لے کر ( جو بظا ہر تاریخی بیان کے
مخالف نظر آتا ہے حالانکہ دراصل وہ بھی تاریخی روایات کے مخالف نہیں ہے بلکہ تاریخ سے ایک زائد بات
بتاتا ہے ) اس بحث میں ساری تاریخی روایات کو عملا ردی کی طرح پھینک دیا ہے.حالانکہ خود قرآن
شریف کے دوسرے حصے ان تاریخی روایات کی تصدیق کرتے ہیں اور سوائے ایک زائد بات کے جس کی
طرف قرآن شریف اشارہ کرتا ہے باقی ساری باتوں میں قرآنی بیان اور تاریخی بیان ایک دوسرے کے
مطابق ہیں اور ہرگز کوئی اختلاف نہیں.تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے تاریخی بیان کا ماحصل جو مضبوط
روایات سے ثابت ہے اور جس کی تائید میں صحیح احادیث بھی پائی جاتی ہیں یہ ہے کہ بدر کے موقع پر مسلمان
صرف قافلہ کی روک تھام کے خیال سے مدینہ سے نکلے تھے اور لشکر قریش کا علم انہیں بدر کے پاس پہنچ کر ہوا تھا
Page 401
۳۸۶
اور اس طرح گویا لشکر قریش اور مسلمانوں کا مقابلہ اچانک ہو گیا تھا.اب اس تاریخی بیان کے مقابلہ میں
ہم قرآن شریف پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے سوسورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكْرِهُونَ )
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ
إحْدَى الصَّابِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللهُ
اَنْ يُحِقَّ الْحَقِّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِينَ.......إِذْ أَنْتُمْ بِالْعَدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمُ
بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعُدِ وَلَكِنْ
ليَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا.....وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ
قَلِيْلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
یعنی ”اے رسول! جس طرح نکالا تجھے تیرے رب نے تیرے گھر (مدینہ ) سے حق کے
ساتھ اس حال میں کہ مومنوں میں سے بعض لوگ تیرے اس نکلنے کو ایک سخت مشکل اور نازک
کام سمجھتے تھے.اسی طرح نکلے تیرے دشمن تجھ سے لڑتے ہوئے حق کے رستہ میں بعد اس کے کہ
وہ حق ان کے لئے ظاہر ہو چکا تھا.( یعنی ان پر خدائی سنت کے مطابق اتمام حجت ہو چکا
تھا ) اور حق کو قبول کرنا ان کے لئے ایسا تھا کہ گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جار ہے ہوں
اور موت بھی وہ جو سامنے نظر آرہی ہو.اور یاد کرواے مسلمانو! جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ وعدہ
دیتا تھا کہ کفار کے دو گروہوں ( یعنی لشکر اور قافلہ ) میں سے کسی ایک گروہ پر ضرور تمہیں غلبہ
حاصل ہوگا اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم خواہش کر رہے تھے کہ ان گروہوں میں سے کم تکلیف اور کم
مشقت والے گروہ ( یعنی قافلہ ) سے تمہارا سا منا ہو، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ لشکر سے تمہارا
مقابلہ کرا کے ) اپنی پیشگوئی کے مطابق حق کو قائم کر دے اور ان کفار مکہ کی جڑ کاٹ ڈالے
یعنی ائمۃ الکفر بلاک کر دیے جائیں جبکہ تم بدر کی وادی کے ورلے کنارے پر پہنچے تھے اور
قریش کا لشکر پر لے کنارے پر تھا ( یعنی تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تھے ) اور قافلہ
تمہارے نیچے (مکہ کی طرف کو ) نکل چکا تھا ( یعنی قافلہ تو بیچ کر نکل گیا اور تم اچانک لشکر کے
سامنے آگئے اور یہ سب کچھ خدائی تصرف کے ماتحت ہو اور نہ ) اگر لڑائی کے وقت کی تعیین تم پر
ا : انفال : ۶ تا ۸
: انفال : ۴۳
۳ : انفال : ۴۵
Page 402
۳۸۷
چھوڑ دی جاتی تو (اس وقت ظاہری اسباب کے لحاظ سے تمہاری حالت ایسی کمزور تھی کہ ) تم
ضرور اس میں اختلاف کرتے ( یعنی گوتم میں سے بعض یہ کہتے کہ ہم ہر حالت میں لڑنے کو تیار
ہیں لیکن ضرور اس بات پر زور دیتے کہ لڑائی کے وقت کو پیچھے ڈال دیا جاوے تا کہ وہ کفار کے
مقابلہ کے لیے اچھی طرح مضبوط ہو جائیں تو پھر لڑائی کے لیے ان کے سامنے آئیں ) لیکن اللہ
کا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں لشکر قریش کے مقابلہ پر لا کر ) وہ کام کر گزرے جس کا فیصلہ پہلے سے ہو
چکا تھا ( یعنی وہ پیشگوئی پوری کرے جو خدائی نشان کے طور پر ائمۃ الکفر کی ہلاکت کے متعلق کی
گئی تھی پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں میں کفار کو
تھوڑا کر کے دکھاتا تھا ( تاکہ تم بد دل نہ ہو ) اور تمہیں کفار کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا
( تا کہ وہ بھی مقابلہ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں) یہ بھی خدا نے اس لیے کیا کہ وہ اس بات کو کر گزرے
جس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا اور بیشک اللہ ہی کی طرف ہر کام کا مال ہے ( یعنی تمام کاموں کا
انتہائی تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ جس طرح چاہے واقعات کو چلا سکتا ہے.)
ان قرآنی آیات سے جو مسلمہ طور پر جنگ بدر کے متعلق تسلیم کی گئی ہیں اور جن کے ترجمہ کی تشریح
کیلئے میں نے بعض الفاظ زائد کر دیئے ہیں مندرجہ ذیل یقینی نتائج پیدا ہوتے ہیں.اوّل.جس وقت آپ مدینہ سے نکلے اس وقت مومنوں میں سے بعض لوگ آپ کے نکلنے کو ایک
مشکل اور نازک کام سمجھتے تھے.دوم.مومنوں کی ( مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کی یا اکثر کی.مگر غالبا اکثر کی ) یہ خواہش تھی کہ قافلہ
کے ساتھ مقابلہ ہو.سوم.یہ خواہش اس لئے نہیں تھی کہ انہیں قافلہ کے اموال و امتعہ کا خیال تھا بلکہ اس لئے تھی کہ قافلہ
والوں کی تعداد تھوڑی تھی اور ان کا سامان حرب بھی کم تھا اس لئے اس کے مقابلہ میں کم تکلیف اور کم مشکل
پیش آنے کا احتمال تھا.چہارم.مگر اللہ تعالیٰ کا شروع سے ہی یہ ارادہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ لشکر قریش کے ساتھ ہو.تا کہ
وہ ائمۃ الکفر جو اپنے مظالم اور سرکشیوں اور خونی کارروائیوں کی وجہ سے ہلاک کئے جانے کے سزاوار
ہو چکے تھے ایک خدائی نشان کے طور پر کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے ہلاک کر دیے جائیں اور وہ پیشگوئی
پوری ہو جوان کی ہلاکت کے متعلق پہلے سے کی جا چکی ہے.
Page 403
۳۸۸
پنجم.اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف کیا کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کا میلان قافلہ کے
مقابلہ کی طرف تھا قافلہ تو بچ کر نکل گیا اور لشکر قریش سے ان کا اچانک سامنا ہو گیا.خشم.یہ تصرف اس لئے کیا گیا کہ مسلمانوں کی حالت اس وقت ظاہری اسباب کے ماتحت اتنی
کمز ور تھی کہ اگر خود ان پر اس لڑائی کے وقت تعیین چھوڑ دی جاتی تو ان میں سے ایک فریق ضرور اس مقابلہ
کے وقت کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتا حالانکہ اللہ کا منشا یہ تھا کہ ابھی مقابلہ ہو اور فیصلہ ہو جائے.ہفتم.یہ خدائی تصرف لشکر قریش اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جانے کے
وقت تک بھی جاری رہا.چنانچہ خدائی تصرف کے ماتحت دونوں فوجیں ایسے طور پر ایک دوسرے کے
سامنے آئیں کہ دونوں ایک دوسرے کو ان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتے تھے اور یہ اس لئے کیا گیا کہ تا
مسلمانوں میں بددلی نہ پیدا ہو اور قریش بھی جرات کے ساتھ آگے بڑھیں اور مقابلہ ہو جاوے.یہ وہ سات باتیں ہیں جو امر زیر بحث کے متعلق قرآن شریف سے یقینی طور پر پتہ لگتی ہیں مگر ہم دیکھتے
ہیں کہ سوائے نمبر اول کے یہ ساری باتیں تاریخی بیان کے عین مطابق ہیں اور ان میں وہی حالات بیان
کئے گئے ہیں جو صحیح تاریخی روایات اور احادیث میں مذکور ہوئے ہیں.پس کوئی وجہ نہیں کہ ہم تاریخی بیان کو
رد کر دیں کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ قرآنی بیان کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس کے رد کرنے سے قرآنی بیان کا رد
لازم آتا ہے.غور کا مقام ہے کہ تاریخی روایات سوائے اس کے اور کیا کہتی ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر قافلہ کے
خیال سے نکلا تھا، مگر اچانک اس کا مقابلہ لشکر قریش سے ہو گیا.مگر کیا قرآن شریف بھی یہی نہیں کہتا کہ
مسلمانوں کو قافلہ کی خواہش تھی ، مگر خدا تعالیٰ نے اس کا مقابلہ اچانک لشکر قریش سے کرا دیا ؟ اور
قرآن شریف اس کی وجہ بھی بتاتا ہے کہ خدا نے یہ کام اپنے خاص تصرف کے ماتحت اس لئے کیا کہ
تا بطور ایک خدائی نشان کے آئمۃ الکفر مسلمانوں کے ہاتھ سے ہلاک کروا دئیے جائیں اور وہ پیشگوئی پوری
ہو جو ان کی ہلاکت کے متعلق پہلے سے کی جاچکی تھی.اندریں حالات اس بات کے ثابت کرنے کی کوشش
کرنا کہ مسلمان مدینہ سے ہی لشکر قریش کے مقابلہ کے لئے نکلے تھے اس بات کے ہم معنی ہے کہ نہ صرف یہ
کہ تاریخ و احادیث کی کثیر التعداد مضبوط اور صحیح روایات کو بالکل ردی کی طرح پھینک دیا جاوے بلکہ اس
قرآنی بیان کو بھی غلط قرار دیا جاوے جسے خدا تعالیٰ نے بدر کے قصہ میں بطور مرکزی نقطہ کے رکھا ہے.پس حق یہی ہے کہ مسلمان قافلہ ہی کی روک تھام کے خیال سے نکلے لیکن جب بدر کے پاس پہنچے تو
اچانک یعنی علی غیر میعاد لشکر قریش کا سامنا ہو گیا اور جیسا کہ ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں قافلہ کی روک تھام
Page 404
۳۸۹
کے لئے نکلنا ہرگز قابل اعتراض نہیں تھا.کیونکہ اول تو یہ مخصوص قافلہ جس کے لئے مسلمان نکلے تھے ایک
غیر معمولی قافلہ تھا جس میں قریش کے ہر مرد و عورت کا تجارتی حصہ تھا لے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے
متعلق روساء قریش کی یہ نیت تھی کہ اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں استعمال کیا جائے
گا.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ یہی منافع جنگ اُحد کی تیاری میں صرف کیا گیا.پس اس قافلہ کی روک
تھام تدابیر جنگ کا ضروری حصہ تھی.دوسر کے عام طور پر بھی قریش کے قافلوں کی روک تھام اس لئے
ضروری تھی کہ چونکہ یہ قافلے مسلح ہوتے تھے اور مدینہ سے بہت قریب ہوکر گزرتے تھے ان سے مسلمانوں
کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا جس کا سد باب ضروری تھا.تیسر کے یہ قافلے جہاں جہاں سے بھی گزرتے تھے
مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں سخت اشتعال انگیزی کرتے پھرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی
حالت نازک ہورہی تھی.پس ان کا راستہ بند کرنا دفاع اور خود حفاظتی کے پروگرام کا حصہ تھا.چوتھے قریش
کا گزارہ زیادہ تر تجارت پر تھا اس لئے ان قافلوں کی روک تھام ظالم قریش کو ہوش میں لانے اور ان کو ان
کی جنگی کارروائیوں سے باز رکھنے اور صلح اور قیام امن کے لئے مجبور کرنے کا ایک بہت عمدہ ذریعہ تھی اور
پھران قافلوں کی روک تھام کی غرض لوٹ مار نہیں تھی بلکہ جیسا کہ قرآن شریف صراحتا بیان کرتا ہے خود اس
خاص مہم میں مسلمانوں کو قافلہ کی خواہش اس کے اموال کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس وجہ سے تھی کہ اس کے
مقابلہ میں کم تکلیف اور کم مشقت کا اندیشہ تھا.اب رہی وہ بات جو قرآن شریف میں تاریخی بیان سے زائد پائی جاتی ہے سو وہ بھی تاریخ کے مخالف
نہیں
کہلا سکتی کیونکہ تاریخی بیان میں کوئی ایسی بات نہیں جو اس کے خلاف ہو البتہ یہ ایک زائد علم ہے جو ہمیں
قرآن شریف سے حاصل ہوتا ہے اور بعض تاریخی روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے مگر
بہر حال یہی ایک بات ہے جو تاریخی نکتہ نگاہ سے قابل تشریح سمجھی جاسکتی ہے اور یہ بات قرآنی بیان کے
مطابق یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو اس وقت بعض مسلمان آپ کی اس مہم کو
ایک مشکل اور نازک کام سمجھتے تھے.اس پر طبعا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے صحابہ
کے دل میں یہ احساس تھا.اگر محض قافلہ کی روک تھام کا خیال ہوتا تو تین سو جانثاروں سے زائد کی جمعیت
کے ہوتے ہوئے یہ احساس ہرگز نہیں ہونا چاہئے تھا.پس معلوم ہوا کہ قافلہ کی خبر کے ساتھ ساتھ کوئی اور
خیال بھی تھا جو بعض مسلمانوں
کو فکر مند کر رہا تھا.یہ خیال کیا تھا ؟ اس سوال کا جواب تاریخ سے واضح طور پر
: ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۷
۲ : ابن سعد جلد ۲ صفحه ۲۵
Page 405
۳۹۰
نہیں ملتا اور نہ ہی قرآن شریف نے اسے صراحتا بیان کیا ہے.پس اس کے متعلق لازماً قیاس کرنا
ہوگا اور خوش قسمتی سے یہ قیاس مشکل نہیں ہے کیونکہ تاریخ و قرآن شریف ہر دو میں قافلہ کے ساتھ ساتھ لشکر
قریش کا ذکر بھی چلتا ہے اور اس سارے قصہ میں اگر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں
فکر پیدا کر سکتی تھی تو وہ لشکر قریش کی اطلاع ہے.پس ماننا پڑے گا کہ مدینہ میں ہی لشکر قریش کی خبر بھی پہنچ
گئی ہوگی.جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فکر دامن گیر ہوا ہوگا کہ اگر لشکر سے مقابلہ ہو گیا تو سخت مشکل کا
سامنا ہوگا.یہ وہ استدلال ہے جو اس آیت سے کیا گیا ہے اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ استدلال ایک عمدہ
استدلال ہے جو اس آیت کی روشنی میں یہ واقعی مانا پڑتا ہے کہ قریش کی آمد آمد کی اطلاع مدینہ میں ہی پہنچے
گئی ہوگی لیکن جو وسعت اس استدلال میں پیدا کر لی گئی ہے وہ ہرگز درست نہیں.یعنی اس آیت سے یہ
نتیجہ نکالنا کہ مدینہ میں ہی سارے یا اکثر مسلمانوں کو یہ اطلاع پہنچ گئی تھی اور وہ سب کے سب یا ان میں
سے اکثر اسی علم کے ماتحت مدینہ سے نکلے تھے.یہ یقیناً غلط ہے کیونکہ علاوہ اس کے قرآن شریف کا بقیہ
بیان اور کثیر التعداد تاریخی روایات اسے قطعی طور پر غلط ثابت کرتی ہیں.خود آیت زیر بحث بھی اس وسعت
کو قبول نہیں کرتی کیونکہ آیت میں یہ صاف طور پر موجود ہے کہ یہ احساس صرف بعض صحابہ کو تھا جیسا کہ
فریقا کے لفظ سے پایا جاتا ہے.یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کے متعلق صرف بعض صحابہ فکر مند
تھے سب یا اکثر صحابہ فکر مند نہ تھے.پس ثابت ہوا کہ قرآن شریف کی رو سے مدینہ میں لشکر قریش کی خبر
صرف بعض صحابہ کو پہنچی تھی اور اکثر اس سے بے خبر تھے اور یہ وہ صورت ہے جو قرآن شریف کے بقیہ بیان
اور تاریخی روایات کے مخالف نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ جب لشکر قریش کی خبر مدینہ میں پہنچی
ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت سے اس کی اطلاع صرف بعض خاص خاص صحابہ کو دی ہو
اور اکثر مسلمان اس سے بے خبر رہے ہوں اور وہ اسی بے خبری کی حالت میں صرف قافلہ کے خیال سے
مدینہ سے نکلے ہوں اور پھر بدر کے پاس پہنچ کر قریش سے اچانک ان کا سامنا ہو گیا ہو.اور یہی صورت
درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن شریف کا بقیہ بیان اس کی تائید میں ہے اور تاریخ و حدیث میں بھی اس
کے متعلق اشارات پائے جاتے ہیں.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکلنے سے قبل خاص طور
پر صحابہ سے مشورہ کرنا اور اس مشورہ کو ایسے رنگ میں چلانا کہ انصار بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں
تا کہ آپ کے ساتھ زیادہ جمعیت ہو.حالانکہ انصار اس سے پہلے کسی مہم میں شامل نہیں ہوئے تھے.صحیح مسلم حالات غزوہ
: ابن سعد
Page 406
۳۹۱
اور پھر جب بدر کے پاس پہنچ کر قریش کے ایک حبشی غلام کے ذریعہ لشکر قریش کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کا اس
کے متعلق شک کرنا اور اسے جھوٹا سمجھنا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً بلا تامل مان لینا اور فرما نا کہ یہ
غلام سچ کہتا ہے.وغیر ذالک.یہ سب اس بات کی شہادتیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے
ہی لشکر قریش کی آمد کی اطلاع تھی مگر صحابہ اس سے بے خبر تھے.سوائے ان خاص خاص صحابہ کے جنہیں
قرآنی بیان کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خبر کی اطلاع ہو گئی ہوگی.اب صرف یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ کیا یہ مکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشکر قریش کی خبر
مدینہ میں ہی مل جاتی اور پھر یہ کہ اگر آپ کو یہ خبر مل گئی تھی تو آپ نے کیوں صرف بعض صحابہ کو اطلاع
دی اور اکثر مسلمان اس سے بے خبر رہے؟ سو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہاں ایسا ممکن تھا کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے اور آپ پر خدا کا کلام نازل ہوتا تھا اور تاریخ سے ثابت
ہے کہ بسا اوقات آپ کو آئندہ ہونے والے واقعات یا غیب کی خبروں سے خدائی وحی کے ذریعہ اطلاع
دی جاتی تھی.پس اگر اس موقع پر بھی آپ کو خدائی الہام کے ذریعہ یہ اطلاع مل گئی ہو کہ قریش کا ایک لشکر
آ رہا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اور آپ کی زندگی کے واقعات کے لحاظ سے یہ ایک نہایت معمولی
واقعہ سمجھا جائے گا.اور چونکہ ایسا الہام جو کسی پیشگوئی کا حامل ہو بعض اوقات تاویل طلب ہوتا ہے اور اس
کی پوری تفہیم بعض اوقات خود ملہم کو بھی واقعہ سے قبل نہیں ہوتی.اس لئے ممکن ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے احتیاطاً اس الہی خبر کی اطلاع صرف خاص خاص صحابہ کو دی ہو اور اکثر مسلمانوں کو اس کی اطلاع
نہ دی گئی ہوتا کہ ان میں اس خبر سے کسی قسم کی بددلی نہ پھلے جیسا کہ قرآن شریف سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اسی
جنگ میں دوسرے موقع پر بددلی کے سدباب کے لئے خدا نے یہ تصرف فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی نظروں
میں کفار کا لشکر ان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتا تھا.دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ظاہری حالات کے لحاظ سے
بھی یہ بات بالکل ممکن تھی کہ آپ کو مدینہ میں ہی لشکر قریش کی اطلاع موصول ہو جاتی.کیونکہ تاریخ سے
ثابت ہے کہ جب ابوسفیان کا قاصد مکہ میں پہنچا تو قریش نے تین دن تیاری میں صرف کئے." اور پھر بدر
تک پہنچنے میں آٹھ یا نو دن مزید لگ گئے.یہ کل گیارہ یا بارہ دن ہوئے.باوجود اس کے جب اسلامی
لشکر بدر میں پہنچا تو لشکر قریش پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں سولہ رمضان
کو پہنچے تھے اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ قریش کا لشکر غالباً پندرہ تاریخ کو وہاں پہنچ گیا ہوگا اب ان پندرہ
سے : صحیح مسلم
: سيرة حلبيه
سے زرقانی
Page 407
۳۹۲
دنوں میں سے گیارہ یا بارہ دن تیاری اور سفر کے نکال دیں تو یہ یقینی نتیجہ نکلتا ہے کہ قریش نے تین یا چار
رمضان کو مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا.دوسری طرف اسلامی لشکر کے مدینہ سے نکلنے کی تاریخ عقلاً بھی
اور روایتہ بھی بارہ رمضان ثابت ہوتی ہے یا گویا قریش کی تیاری اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج
از مدینہ کے درمیان پورے آٹھ یا نو دن کا وقفہ تھا.اس عرصہ میں لشکر قریش کی اطلاع بڑی آسانی کے
ساتھ مدینہ میں پہنچ سکتی تھی بلکہ یہ عرصہ ایک شخص کے مکہ سے مدینہ جانے اور مدینہ سے پھر مکہ واپس آجانے
کے لئے بھی کافی تھا.کیونکہ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ ایک تیز روسوار جو ہر قسم کے بوجھوں سے آزاد
ہو تیسرے چوتھے دن مکہ سے مدینہ پہنچ جاتا تھا.تے
اور اگر یہ سوال ہو کہ مکہ سے اطلاع دینے والا کون تھا ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علاوہ اس کے کہ ابھی
تک مکہ میں بعض کمزور اور غریب مسلمان موجود تھے جو اس قسم کے خطرات کی حالت میں خبر رسانی کا انتظام
کر سکتے تھے.ابھی تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا عباس بن عبدالمطلب بھی مکہ میں ہی تھے
اور تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ ہر قسم کی ضروری خبریں مکہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا کرتے تھے.کے
چنانچہ غزوہ احد کے متعلق تو خاص طور پر یہ ذکر آتا ہے کہ عباس نے اس موقع پر لشکر قریش کی خبر آ نحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو مخفی طور پر بھجوائی تھی اور قاصد سے یہ شرط کی تھی کہ وہ تین دن کے اندر اندر یہ خبر مدینہ پہنچا
دے گا.چنانچہ یہ قاصد واقعی تین دن میں مدینہ پہنچ گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر قریش کی
بر وقت اطلاع ہو گئی اور آپ نے شروع شروع میں یہ خبر صرف خاص خاص صحابہ پر ظاہر فرمائی اور بعد میں
اعلان کیا.ان حالات میں کیا یہ قرین قیاس نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اغلب نہیں ہے کہ بدر کے موقع پر بھی
عباس کی کوئی مخفی تحریر آپ کو پہنچ گئی ہو اور آپ نے اس خیال سے کہ مسلمانوں میں بددلی نہ پیدا ہو اس کا
ذکر صرف خاص خاص صحابہ سے فرمایا اور عامتہ المسلمین سے اس خبر کو مخفی رکھا ہو؟ بلکہ ان حالات کی وجہ سے
جواو پر بیان ہو چکے ہیں بدر کے موقع پر اس قسم کا پردہ رکھنا زیادہ ضروری تھا اور پھر یہ راز داری بدر میں اُحد
کی نسبت آسان بھی زیادہ تھی کیونکہ اس موقع پر قافلہ کی آمد کی خبر بھی ساتھ موجود تھی جس کی وجہ سے لشکر
قریش کی خبر آسانی کے ساتھ اور آخر وقت تک پردہ میں رکھی جاسکتی تھی.اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں
اُحد کے موقع پر عباس کی چٹھی کی خبر ظاہر ہوگئی کیونکہ گو شروع میں راز رکھا جا سکتا تھا لیکن بالآخر اس کے
ابن سعد
: زرقانی حالات غزوہ احد
اسد الغابہ حالات عباس و مواہب اللہ نیہ حالات غزوہ بدر : زرقانی و ابن سعد و واقدی
Page 408
۳۹۳
اظہار کے بغیر چارہ نہیں تھا.بدر کے موقع پر یہ خبر آخر وقت تک بالکل پردہ میں رہی اور ممکن ہے بلکہ اغلب
ہے کہ خدائی منشاء کے ماتحت جس کا قرآن شریف میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے آخری وقت تک یہ پردہ رکھنا ضروری خیال کیا ہو.خلاصہ کلام یہ کہ قرآن شریف اور تاریخ وحدیث کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو عام مؤرخین
کا یہ خیال درست ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کے سارے مسلمان محض قافلہ کے خیال
سے مدینہ سے نکلے تھے اور لشکر قریش کی اطلاع سے وہ
سے وہ سب قطعی طور پر بے خبر تھے اور نہ ہمارے
جدید محققین کی یہ رائے درست ہے کہ مدینہ میں ہی سارے مسلمانوں کو شکر قریش کی آمد کی اطلاع ہو گئی تھی
اور وہ اس اطلاع کے بعد مدینہ سے نکلے تھے بلکہ حق یہ ہے کہ پیشتر اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ سے نکلتے لشکر اور قافلہ دونوں کی اطلاع آپ کو پہنچ چکی تھی.مگر لشکر کی آمد مصلحنا بصیغہ راز رکھی گئی
اور سوائے بعض خاص خاص صحابہ کے جو غالباً صرف اکابر مہاجرین میں سے تھے باقی سارے مسلمان اس
سے بالکل بے خبر رہے اور اسی بے خبری کی حالت میں وہ مدینہ سے نکلے حتی کہ بدر کے پاس پہنچ کر لشکر
قریش سے ان کا اچانک سامنا ہو گیا.واللہ اعلم.یہ سوال کہ کفار کی طرف سے جنگ بدر کا سبب کیا تھا یعنی لشکر قریش مکہ سے کس غرض وغایت کے
ما تحت نکلا تھا.اس کے متعلق قرآن شریف مندرجہ ذیل صداقت پیش کرتا ہے.وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْدٌ o یعنی اے مسلمانو! تم ان کفار کی طرح مت
بنو جو اپنے گھروں سے تکبر اور نمائش کا اظہار کرتے ہوئے نکلے تھے اور ان کی غرض یہ تھی کہ اللہ کے دین
کے رستے میں جبری طور پر روکیں پیدا کریں.مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی کارروائیوں کا محاصرہ کر کے انہیں
خائب و خاسر کر دیا.“
اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ خواہ تحریکی سبب کوئی ہوا ہو اس مہم میں قریش مکہ کی اصل غرض وغایت ان
کے ان خونی ارادوں پر مبنی تھی جو وہ شروع سے اسلام اور بانی اسلام کے متعلق رکھتے تھے اور قافلہ کی حفاظت
یا عمرو بن حضرمی کے قتل کے انتقام کا خیال محض ایک آلہ تھا جس سے وہ عوام کو اشتعال دلانے اور ان کے
جوشوں
کو قائم رکھنے کا کام لیتے تھے اور تاریخ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے.چنانچہ قافلہ کے خطرے کی
: سورۃ انفال : ۴۸
Page 409
۳۹۴
اطلاع آنے پر بجائے اس کے کہ قریش جلدی سے نکل کھڑے ہوتے ان کا پورے ساز وسامان اور پوری
تیاری کے ساتھ تین دن کے بعد نکلنا اور راستہ میں قافلہ کے بچ کر نکل جانے کی اطلاع آجانے پر بھی بڑی
رعونت کے ساتھ آگے بڑھنے پر اصرار کرنا اور پھر عین میدان جنگ میں پہنچ کر جب کہ بعض لوگوں کی طرف
سے جنگ کے روک دیئے جانے کی تحریک ہوئی ابو جہل وغیرہ کا نہایت سختی کے ساتھ لڑنے پر اصرار کرنا
اور سارے لوگوں کا اسی کی تائید میں ہونا یہ سب اس بات کی یقینی شہادتیں ہیں کہ دراصل قافلہ کی حفاظت
اور عمرو بن حضرمی کے قتل کے انتقام کا خیال ایک محض بہا نہ تھا اور اصل غرض اسلام کو مٹانا اور مسلمانوں
کو نیست و نابود کر ناتھی.اس اصولی بحث کے بعد ہم جنگ بدر کے حالات کا بیان شروع کرتے ہیں.مگر ہم ناظرین سے
استدعا کریں گے کہ ہماری اس اصولی بحث کو بدر کے حالات کے مطالعہ کے بعد ایک دفعہ پھر ملاحظہ
فرما ئیں کیونکہ جنگ بدر کے حالات معلوم ہونے پر یہ بحث زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آسکتی ہے.
Page 410
۳۹۵
جنگ بدر
اسلامی سلطنت کا استحکام
اور
رؤساء قریش کی تباہی
جنگ بدر - رمضان ۲ ہجری مطابق مارچ ۶۲۴ء اب ہم جنگ بدر کے حالات کا ذکر شروع کرتے
ہیں.یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ ہجرت نبوی کے
بعد قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی تیاری شروع کر دی تھی اور اس
دوران میں سر یہ وادی نخلہ میں جو عمرو بن حضرمی کے قتل کا واقعہ ہوا تھا اس سے رؤساء قریش نے
ناجائز فائدہ اٹھا کر عامۃ الکفار کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت کی آگ کو اور بھی زیادہ خطر ناک طور پر
شعلہ زن کر دیا تھا اور اس شخص کی طرح جسے اپنے وہ مظالم تو بھول جاتے ہیں جو وہ خود دوسروں پر کرتا رہا
ہے لیکن اگر کسی دوسرے کی طرف سے اسے ذراسی بھی تکلیف پہنچ جاوے تو وہ اسے ہمیشہ یا درکھتا ہے.خواہ
وہ جوابی رنگ ہی رکھتی ہو.قریش مکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان
کو تباہ و برباد کر دینے کی تیاری میں پہلے سے
بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ منہمک ہو گئے تھے.اسی اثناء میں مدینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس کے ساتھ تمیں چالیس یا بعض روایات کی رو
سے ستر آدمی تھے ابوسفیان کی سرداری میں شام کی طرف سے مکہ کو واپس آ رہا ہے.اس قافلہ میں غیر معمولی
طور پر قریش کے ہر مرد عورت کا حصہ تھا بلکہ لکھا ہے کہ جو چیز اور جو رقم بھی وہ تجارت میں لگا سکتے تھے وہ اس
موقع پر انہوں نے لگا دی تھی.یا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالبا اس تجارت کے منافع کے متعلق قریش کا یہ
فیصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی مصارف میں خرچ ہوگا.چونکہ قافلوں کی روک تھام ظالم قریش کو
ابن ہشام و زرقانی
: ابن سعد حالات غزوہ بدر
Page 411
۳۹۶
ہوش میں لانے اور انہیں ان کی خطرناک کارروائیوں سے روکنے کا ایک بہترین ذریعہ تھی اور دوسرے ان
قافلوں کا مدینہ سے اس قدر قریب ہو کر گزرنا ویسے بھی مسلمانوں کے لئے کئی طرح سے خطرے کے
احتمالات رکھتا تھا اور پھر اس قافلہ کے خاص حالات ایسے تھے کہ اس کا بیچ کر نکل جانا بظاہر حالات
مسلمانوں کی تباہی کا پیش خیمہ سمجھا جاسکتا تھا.اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پا کر اپنے دو
مہاجر صحابی طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو خبر رسانی کے لئے روانہ فرمایا اور دوسرے صحابہ کو بھی اطلاع
دے دی کہ وہ اس قافلہ کی روک تھام کے لئے نکلنے کو تیار رہیں مگر اتفاق ایسا ہوا کہ کسی طرح ابو سفیان کو بھی
آپ کے اس ارادے کی اطلاع ہوگئی یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ویسے ہی بطور خود اندیشہ محسوس کیا ہو.بہر حال اس نے ایک سوار مضمضم نامی مکہ کی طرف بھگا دیا اور اسے تاکید کی کہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا
ہوا مکہ میں پہنچے اور وہاں سے قریش کا لشکر قافلہ کی حفاظت اور مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے نکال
لائے اور خود ابوسفیان نے یہ احتیاط اختیار کی کہ اصل راستے کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے کی طرف ہٹ گیا
اور چھپ چھپ کر مگر تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا.جب ابوسفیان کا یہ قاصد مکہ پہنچا تو اس
نے عرب کے دستور کے مطابق ایک نہایت وحشت زده حالت بنا کر زور زور سے چلانا شروع کیا کہ اے
اہل مکہ تمہارے قافلہ پر محمد اور اس کے اصحاب حملہ کرنے کے لئے نکلے ہیں چلو اور اسے بچالو.یہ خبر سن کر
مکہ کے لوگ گھبرا کر کعبۃ اللہ کے گرد جمع ہو گئے اور رؤساء قریش نے پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے
ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہایت درجہ اشتعال انگیز تقریریں کیں جس سے لوگوں کے سینے
اسلام کی عداوت کے جوش سے بھر گئے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر تباہ و برباد کر دینے کا پختہ
عزم کر لیا.اس وقت قریش کے جوش کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بالا تفاق یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑا جرار لشکر تیار
کر کے مسلمانوں کے خلاف نکلیں اور اس مہم میں ہر وہ شخص جولڑنے کے قابل ہے شامل ہو جو شخص کسی
مجبوری کی وجہ سے خود شامل نہ ہو سکتا ہو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو بھیجنے کا انتظام کرے.اور رؤساء
قریش اس تحریک میں خود سب سے آگے آگے تھے.صرف دو شخص تھے جنہوں نے اس مہم میں شمولیت سے
تأمل کیا اور وہ ابولہب اور امیہ بن خلف تھے مگر ان کے تأمل کی وجہ مسلمانوں کی ہمدردی نہیں تھی بلکہ
ابولہب تو اپنی بہن عاتکہ بنت عبدالمطلب کے خواب سے ڈرتا تھا جو اس نے ضمضم کے آنے سے صرف
تین دن پہلے قریش کی تباہی کے متعلق دیکھا تھا اور امیہ بن خلف اس پیشگوئی کی وجہ سے خائف تھا جو
ا : یہ بالکل جھوٹ تھا کیونکہ ابھی تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی تھے.
Page 412
۳۹۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہونے کے متعلق فرمائی تھی اور جس کا علم اسے سعد بن معاذ کے
ذریعہ مکہ میں ہو چکا تھا لیکن چونکہ ان دونا می رؤساء کے پیچھے رہنے سے عامتہ الکفار پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ
تھا اس لئے دوسرے رؤساء قریش نے جوش اور غیرت دلا دلا کر آخر ان دونوں کو رضامند کر لیا یعنی امیہ تو
خود تیار ہو گیا اور ابولہب نے ایک دوسرے شخص کو کافی روپیہ دینا کر کے اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور اس طرح
تین دن کی تیاری کے بعد ایک ہزار سے زائد جانباز سپاہیوں کا لشکر مکہ سے نکلنے کو تیار ہو گیا.ابھی یہ لشکر مکہ میں ہی تھا کہ بعض رؤساء قریش کو یہ خیال آیا کہ چونکہ بنو کنانہ کی شاخ بنو بکر کے ساتھ
اہل مکہ کے تعلقات خراب ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر وہ ان کے پیچھے مکہ
پر حملہ کر دیں اور اس خیال کی وجہ سے بعض قریش کچھ متزلزل ہونے لگے.مگر بنو کنانہ کے ایک رئیس
سراقہ بن مالک بن جعشم نے جو اس وقت مکہ میں تھا ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ میں اس بات کا ضامن
ہوتا ہوں کہ مکہ پر کوئی حملہ نہیں ہوگا.بلکہ سراقہ کو مسلمانوں کی مخالفت کا ایسا جوش تھا کہ قریش کی اعانت میں
وہ خود بھی بدر تک گیا، لیکن وہاں مسلمانوں کو دیکھ کر اس پر کچھ ایسا رعب طاری ہوا کہ جنگ سے پہلے
ہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ آیا.اسی واقعہ کی طرف قرآن شریف کی اس آیت میں اشارہ سمجھا گیا
ہے کہ اِذْزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ....وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.جبکہ شیطان قریش مکہ
کو مسلمانوں کے خلاف حق بجانب قرار دیتا تھا اور انہیں ابھارتا تھا.الخ
مکہ سے نکلنے سے پہلے قریش نے کعبہ میں جا کر دعا کی کہ اے خدا ہم دونوں فریقوں میں سے جو
گر وہ حق پر قائم ہے اور تیری نظروں میں زیادہ شریف اور زیادہ افضل ہے تو اس کی نصرت فرما اور دوسرے
کو ذلیل ورسوا کر ، اس کے بعد کفار کا لشکر بڑے جاہ وحشم کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا.تمام رؤساء قریش
ساتھ تھے اور گانے بجانے والی عورتیں بھی جو اپنے اشعار کے ساتھ دفیں بجاتی ہوئی غیرت اور جوش دلاتی
تھیں ہمراہ تھیں.راستہ میں رؤساء قریش نے اس مہم کو ایک خاص قومی کارنامہ خیال کرتے ہوئے اپنے
خرچ سے لشکر کی خوراک کا انتظام کیا.چنانچہ ان کی طرف سے ہر روز باری باری نونو دس دس اونٹ
سپاہیوں کی ضیافت کے لئے ذبح کئے جاتے تھے.جب یہ لشکر جحفہ میں پہنچا جو مکہ اور بدر کے درمیان
مگر بدر کے قریب تر ایک مقام ہے تو ابوسفیان کے ایک قاصد کے ذریعے انہیں یہ خبر موصول ہوئی کہ ان کا
زرقانی وسيرة حلبيه
: خمیس جلد اصفحہ ۴۱۷
: سورۃ انفال : ۴۹
زرقانی حالات غزوہ بدر
Page 413
۳۹۸
،،
قافلہ خطرہ کی جگہ سے بچ کر نکل گیا ہے اور اس لئے اب لشکر کو آگے جانے کی ضرورت نہیں.اس خبر پر بعض
لوگ واپس جانے کو تیار ہو گئے لیکن ابو جہل اور اس کی پارٹی کے اثر کے ماتحت اکثر اہل لشکر نے جن کی
نیتیں کچھ اور تھیں بلکہ ایک روایت کی رو سے سب نے لے بڑی سختی سے انکار کیا اور کہا کہ ”خدا کی قسم ہم بدر
تک ضرور جائیں گے اور وہاں جا کر تین دن تک جشن منائیں گے تا کہ ہمیشہ کے لئے ملک میں ہمارا رعب
بیٹھ جاوے اور لوگ ہم سے ڈرنے لگ جائیں.چنانچہ سوائے چند آدمیوں کے جو واپس لوٹ گئے.کے
باقی سارالشکر بڑے کروفر کے ساتھ آگے بڑھا اور مکہ سے نکلنے کی تاریخ سے نویں دن (ایک دن درمیان
میں راستہ کھوئے جانے کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا." ) یعنی ضمضم کی اطلاع پہنچنے کے گیارہ یا بارہ دن
کے بعد بدر کی وادی کے ورلے کنارے پر پہنچا اور وہاں ڈیرے ڈال دئے.اس وقت لشکر قریش کی تعداد
ایک ہزار نفوس پر مشتمل تھی اور یہ لوگ رائج الوقت سامان حرب سے خوب آراستہ تھے.چنانچہ فوج میں
سواری کے سات سواونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے اور سب سوار اوراکثر پیادہ زرہ پوش تھے اور دیگر
سامان جنگ بھی مثلاً نیزہ اور تلوار اور تیر کمان وغیرہ کافی تعداد میں موجود تھا.اب ہم تھوڑی دیر کے لئے لشکر قریش سے جدا ہو کر مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا
ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کے قافلہ کی خبر پا کر اپنے دو صحابی اطلاع حالات کے لئے
روانہ فرما دئے تھے لیکن ابھی وہ واپس نہیں لوٹے تھے کہ آپ کو کسی ذریعہ سے مخفی طور پر یہ اطلاع بھی پہنچ
گئی کہ قریش کا ایک جرار لشکر مکہ سے آ رہا ہے.اس وقت جو کمزور حالت مسلمانوں کی تھی اسے ملحوظ رکھتے
ہوئے نیز جنگی تدابیر کے عام اصول کے مطابق آپ نے اس خبر کو مشتہر نہیں ہونے دیا تا کہ عامتہ المسلمین
میں اس کی وجہ سے کسی قسم کی بددلی نہ پیدا ہو لیکن ایک بیدار مغز جرنیل کی طرح آپ نے بغیر اس خبر کے
اظہار کے ایسے رنگ میں صحابہ میں تحریک فرمائی کہ بہت سے صحابہ باوجود یہ خیال رکھنے کے کہ یہ ہم قافلہ کی
طبری صفحه ۱۲۸۸ وا ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۷
یا درکھنا چاہئے کہ بدر یک وادی کا نام ہے جس میں چند چشمے ہیں اور جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے.اس کی
مسافت عام حالات میں مدینہ سے چار پانچ یوم اور مکہ سے آٹھ نو یوم کی کبھی جاتی ہے.زمانہ جاہلیت میں یہاں ہر سال
ایک میلہ لگا کرتا تھا جس میں عرب کے مختلف قبائل جمع ہو کر تجارت کرتے اور جشن مناتے تھے.پس کفار مکہ نے اس میلہ
کی آڑرکھ کر یہ اصرار کیا کہ ہم بدر تک ضرور جائیں گے تا کہ ہمارا رعب بیٹھ جاوے.روایات میں واپس لوٹ جانے والوں میں قبیلہ بنو عدی اور زہرہ کا نام مذکور ہوا ہے.زرقانی
Page 414
۳۹۹
روک تھام کی غرض سے اختیار کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے حتیٰ کہ انصار بھی جو بیعت
عقبہ ثانیہ کے معاہدے کے موافق صرف مدینہ پر حملہ ہونے کی صورت میں آپ کی حفاظت کے ذمہ دار
سمجھے جاتے تھے اور جو اس وقت تک کسی غزوہ یا سر یہ میں شامل نہیں ہوئے تھے.شریک جہاد ہونے کے
لئے آمادہ ہو گئے.چنانچہ روایت آتی ہے کہ آپ نے مدینہ میں ایک مجلس قائم کی اور صحابہ سے مشورہ
دریافت فرمایا.حضرت ابو بکر و عمر نے جان نثارانہ تقریریں کیں مگر آپ نے ان کی طرف کچھ التفات نہ کیا
جس پر رؤساء انصار سمجھ گئے کہ آپ کا روئے سخن ان کی طرف ہے.چنانچہ ان میں سے سعد بن عبادہ رئیس
خزرج نے جان نثارانہ تقریر کی اور عرض کیا یا رسول
اللہ! انصار ہر خدمت کے لئے حاضر ہیں اور جہاں بھی
آپ ارشاد فرمائیں جانے کے لئے تیار ہیں.اس کے بعد آپ نے صحابہ میں عام تحریک فرمائی اور
انصار ومہاجرین کی ایک جمعیت آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئی ہے لیکن پھر بھی چونکہ عام خیال قافلہ کے
مقابلہ کا تھا بہت سے صحابہ یہ خیال کر کے کہ محض قافلہ کی روک تھام کا معاملہ ہے جس کے لئے زیادہ لوگوں
کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے شامل نہیں ہوئے.دوسری طرف وہ بعض خاص صحابہ جن کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے لشکر قریش کی آمد کا علم ہو گیا تھا مگر جن کو اخفاء راز کا حکم تھا وہ اپنی جگہ فکرمند تھے کہ
دیکھئے اس موقع پر جبکہ لشکر قریش سے بھی مٹھ بھیڑ ہو جانے کا احتمال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
حفاظت کی اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں یا نہیں.چنانچہ انہی لوگوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن
شریف فرماتا ہے اِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ " یعنی مدینہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
نکلنے کو مومنوں کا ایک فریق ( اپنی ظاہری طاقت کا خیال کرتے ہوئے ) پسند نہیں کرتا تھا اور اسے ایک مشکل
اور نازک کام سمجھتا تھا.مگر چونکہ ان کے آقا کا یہی منشاء تھاوہ دلی جوش کے ساتھ لبیک لبیک کہتے ہوئے
اٹھ کھڑے ہوئے.اس وقت تک گو وہ دو صحابی جن کو آپ نے خبر رسانی کے واسطے بھیجا تھا واپس نہیں
لوٹے تھے مگر چونکہ لشکر قریش کی اطلاع آچکی تھی آپ نے مزید توقف کرنا مناسب خیال نہ کیا.اور بارہ
رمضان کو بروز اتوار مدینہ سے انصار و مہاجرین کی ایک جمعیت کے ساتھ اللہ کا نام لیتے ہوئے روانہ
ہو گئے.اکا برصحابہ میں سے جو لوگ اس غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے ان میں سے حضرت عثمان بن عفان
کا نام خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے.ان ایام میں چونکہ ان کی زوجہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت
ل ابن سعد و طبری
: سورۃ انفال : ۶
ے مسلم وابوداؤد
: ابن سعد وزرقانی
: طبری وابن ہشام
Page 415
۴۰۰
بیمار تھیں.اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود حکم دیا تھا کہ وہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ
میں ہی ٹھہریں.اسی طرح قبیلہ خزرج کے رئیس اعظم سعد بن عبادہ بھی عین وقت پر بیمار ہو جانے کی وجہ
سے شامل نہیں ہو سکے یا قبیلہ اوس کے رئیس اسید بن الحضیر بھی کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں
ہوئے.طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید چونکہ ابھی تک خبر رسانی کی مہم سے واپس نہیں آئے تھے اس لیے وہ
بھی لڑائی کی عملی شرکت سے محروم رہ گئے باقی اکثرا کا بر صحابہ آپ کے ہمرکاب تھے.مدینہ سے تھوڑی دور نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرہ ڈالنے کا حکم دیا اور فوج کا جائزہ لیا.کم عمر بچے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی کے شوق میں ساتھ چلے آئے تھے ، واپس کئے گئے.سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بھی کم سن تھے.انہوں نے جب بچوں کی واپسی کا حکم سنا تو لشکر
میں اِدھر اُدھر چھپ گئے لیکن آخر ان کی باری آئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کا حکم
دیا.یہ حکم سن کر عمیر رونے لگ گئے اور آپ نے ان کے غیر معمولی شوق کو دیکھ کر انہیں اجازت دے دی ہے
اب لشکر اسلامی کی تعداد کچھ اوپر تین سو دس
تھی.جن میں مہاجرین کچھ اوپر ساٹھ تھے اور باقی سب انصار تھے..مگر بے سروسامانی کا یہ عالم تھا کہ ساری فوج میں صرف ستر اونٹ اور دوگھوڑے تھے اور انہی پر مسلمان
باری باری سوار ہوتے تھے حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کوئی الگ سواری نہیں تھی یعنی آپ
کو بھی دوسروں کے ساتھ باری باری سے چڑھنا اور اترنا پڑتا تھا.آپ کے ساتھیوں نے بڑے اصرار
سے عرض کیا کہ ہم پیدل چلتے ہیں حضور سوار رہیں، مگر آپ نے نہ مانا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں تم
سے چلنے میں کمزور نہیں ہوں اور ثواب کی خواہش بھی مجھے کسی سے کم نہیں پھر میں کیوں نہ باری میں حصہ
لوں کے لشکر میں زرہ پوش صرف چھ سات تھے اور باقی سامانِ حرب بھی بہت تھوڑا اور ناقص تھا.الغرض
جائزہ وغیرہ کے کام سے فارغ ہو کر آپ آگے روانہ ہوئے.ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ایک شخص نے
جو مشرک تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ چل کر جنگ میں شریک ہونا
چاہتا ہوں.صحابہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ شخص اپنی بہادری اور شجاعت میں شہرت رکھتا
تھا.مگر آپ نے یہ فرما کر اسے رد کر دیا کہ میں اس موقع پر ایک مشرک سے مدد نہیں لینا چاہتا.تھوڑی دیر
بعد وہ شخص پھر آیا لیکن ادھر سے پھر وہی جواب تھا.تیسری دفعہ وہ پھر حاضر ہوا اور اپنی خدمات پیش کیں
زرقانی
سے بخاری غزوہ بدر
: اصابہ ذکر عمیر بن ابی وقاص
ابن سعد
Page 416
۴۰۱
اور ساتھ ہی عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں.آپ نے فرمایا.ہاں اب بڑی خوشی
سے ہمارے ساتھ چلو
مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ کا امیر مقرر کیا تھا.مگر جب آپ
روحاء کے قریب پہنچے جو مدینہ سے ۳۶ میل کے فاصلہ پر ہے تو غالبا اس خیال سے کہ عبداللہ ایک نابینا
آدمی ہیں اور لشکر قریش کی آمد آمد کی خبر کا تقاضا ہے کہ آپ کے پیچھے مدینہ کا انتظام مضبوط رہے آپ نے
ابولبابہ بن منذر کو مدینہ کا امیر مقرر کر کے واپس بھیجوا دیا اور عبد اللہ بن ام مکتوم کے متعلق حکم دیا کہ وہ
صرف امام الصلوۃ رہیں مگر انتظامی کام ابولبابہ سرانجام دیں.مدینہ کی بالائی آبادی یعنی قبا کے لئے آپ نے
عاصم بن عدی کو الگ امیر مقرر فرمایا.اسی مقام سے آپ نے بسیس اور عدی نامی دو صحابیوں کو دشمن کی
حرکات وسکنات کا علم حاصل کرنے کے لئے بدر کی طرف روانہ فرمایا اور حکم دیا کہ وہ بہت جلد خبر لے کر
واپس آئیں تے روحاء سے آگے روانہ ہو کر جب مسلمان وادی صفراء کے ایک پہلو سے گزرتے ہوئے
زفران میں پہنچے جو بدر سے صرف ایک منزل ورے ہے تو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ قافلہ کی حفاظت کے
لئے قریش کا ایک بڑا جرار لشکر مکہ سے آرہا ہے.اب چونکہ اخفاء راز کا موقع گزر چکا تھا.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے انہیں اس خبر سے اطلاع دی اور پھر ان سے مشورہ پوچھا کہ اب کیا کرنا
چاہئے.بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ظاہری اسباب کا خیال کرتے ہوئے تو یہی بہتر معلوم ہوتا
ہے کہ قافلہ سے سامنا ہو کیونکہ لشکر کے مقابلہ کے لئے ہم ابھی پوری طرح تیار نہیں ہیں.مگر آپ نے اس
رائے کو پسند نہ فرمایا.دوسری طرف اکابر صحابہ نے یہ مشورہ سنا تو اٹھ اٹھ کر جاں نثارا نہ تقریریں کیں اور
عرض کیا ہمارے جان و مال سب خدا کے ہیں.ہم ہر میدان میں ہر خدمت کے لئے حاضر ہیں.چنانچہ
مقداد بن اسود نے جن کا دوسرا نام مقداد بن عمرو بھی تھا کہا یا رسول اللہ ! ہم موسیٰ کے اصحاب کی طرح
نہیں ہیں کہ آپ کو یہ جواب دیں کہ جا تو اور تیرا خدا جا کر لڑو ہم یہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ
جہاں بھی چاہتے ہیں چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ہو کر
لڑیں گے.آپ نے یہ تقریر سنی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتمانے لگ گیا.مگر اس موقع پر بھی
آپ انصار کے جواب کے منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ وہ بھی کچھ بولیں.کیونکہ آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید
لے مسلم آخر ابواب الجهاد والسیر
۴ : بخاری کتاب المغازی
ابن ہشام
: تاریخ الخمیس
Page 417
۴۰۲
انصار یہ سمجھتے ہوں کہ بیعت عقبہ کے ماتحت ہمارا فرض صرف اس قدر ہے کہ اگر عین مدینہ پر کوئی حملہ ہوتو
اس کا دفاع کریں.چنانچہ باوجود اس قسم کی جاں نثارا نہ تقریروں کے آپ یہی فرماتے گئے کہ اچھا پھر مجھے
مشورہ دو کہ کیا کیا جاوے.سعد بن معاذ رئیس اوس نے آپ کا منشاء سمجھا اور انصار کی طرف سے عرض
کیا یا رسول اللہ ! شاید آپ ہماری رائے پوچھتے ہیں.خدا کی قسم جب ہم آپ کو سچا سمجھ کر آپ پر ایمان
لے آئے ہیں اور ہم نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو پھر اب آپ جہاں چاہیں چلیں ہم آپ
کے ساتھ ہیں اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں
کود جانے کو کہیں تو ہم کو د جائیں گے اور ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا اور آپ انشاء اللہ ہم کو
لڑائی میں صابر پائیں گے اور ہم سے وہ بات دیکھیں گے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی.آپ نے
یہ تقریرسنی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا.سِيرُوا وَابْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
وَاللَّهِ لَكَانِي انْظُرُ إِلى مَصَارِعَ الْقَوْمِ یعنی تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھوا اور خوش ہو کیونکہ اللہ
نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے ان دو گروہوں ( یعنی لشکر اور قافلہ ) میں سے کسی ایک گروہ پر وہ ہم کو
ضرور غلبہ دے گا.اور خدا کی قسم میں گویا اس وقت وہ جگہیں دیکھ رہا ہوں جہاں دشمن کے آدمی قتل ہو ہو کر
گریں گے.آپ کے یہ الفاظ سن کر صحابہ خوش ہوئے مگر ساتھ ہی انہوں نے حیران ہوکر عرض کیا ھلا
ذَكَرُتَ لَنَا الْقِتَالَ فَنَسْتَعِدَ - یعنی "یا رسول اللہ! اگر آپ کو پہلے سے لشکر قریش کی اطلاع تھی تو آپ
نے ہم سے مدینہ میں ہی جنگ کے احتمال کا ذکر کیوں نہ فرما دیا کہ ہم کچھ تیاری تو کر کے نکلتے.“ مگر با وجود
اس خبر اور اس مشورہ کے اور باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خدائی بشارت کے کہ ان
دوگروہوں میں سے کسی ایک پر مسلمانوں
کو ضرور فتح حاصل ہوگی ابھی تک مسلمانوں کو معین طور پر یہ معلوم نہیں
ہوا تھا کہ ان کا مقابلہ کس گروہ سے ہوگا اور وہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ مٹھ بھیٹر
ہو جانے کا امکان سمجھتے تھے اور وہ طبعاً کمزور گروہ یعنی قافلہ کے مقابلہ کے زیادہ خواہش مند تھے.اس مشورہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنے شروع ہوئے
اور جب آپ بدر کے قریب پہنچے تو کسی خیال کے ماتحت جس کا ذکر روایات میں نہیں ہے آپ حضرت
ابوبکر صدیق کو اپنے پیچھے سوار کر کے اسلامی لشکر سے کچھ آگے نکل گئے.اس وقت آپ کو ایک بوڑھا
بدوی ملا جس سے آپ کو باتوں باتوں میں یہ معلوم ہوا کہ اس وقت قریش کا لشکر بدر کے بالکل پاس پہنچا ہوا
ابن ہشام وابن سعد
: ابن كثير وسيرة حلبيه
Page 418
۴۰۳
ہے.آپ یہ خبر سن کر واپس تشریف لے آئے اور حضرت علی اور زبیر بن العوام اور سعد بن وقاص وغیرہ
کو دریافت حالات کے لئے آگے روانہ فرمایا.جب یہ لوگ بدر کی وادی میں گئے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں
کہ مکہ کے چند لوگ ایک چشمہ سے پانی بھر رہے ہیں.ان صحابیوں نے اس جماعت پر حملہ کر کے ان میں
سے ایک حبشی غلام کو پکڑ لیا اور اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے.اس وقت آپ نماز
میں مصروف تھے.صحابہ نے یہ دیکھ کر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں مصروف ہیں، خود اس غلام
سے پوچھنا شروع کیا کہ ابوسفیان کا قافلہ کہاں ہے.یہ حبشی غلام چونکہ لشکر کے ہمراہ آیا تھا اور قافلہ سے
بے خبر تھا اس نے جواب میں کہا کہ ابوسفیان کا تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ ابوالحکم یعنی ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ
اور امیہ وغیرہ اس وادی کے دوسرے کنارے ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں.صحابہ نے جن کا میلان قافلہ کی
طرف زیادہ تھا سمجھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور دیدہ دانستہ قافلہ کی خبر کو چھپانا چاہتا ہے.جس پر بعض لوگوں
نے اسے کچھ زدو کوب کیا لیکن جب وہ اسے مارتے تھے تو وہ ڈر کے مارے کہہ دیتا تھا کہ اچھا میں بتاتا
ہوں اور جب اسے چھوڑ دیتے تھے تو پھر وہی پہلا جواب دیتا تھا کہ مجھے ابوسفیان کا تو کوئی علم نہیں ہے
البتہ ابوجہل وغیرہ یہ پاس ہی موجود ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ باتیں سنیں تو آپ نے
جلدی سے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کو مارنے سے روکا اور فرمایا.جب وہ سچی بات بتا تا ہے تو تم اسے
مارتے ہو اور جھوٹ کہنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتے ہو..پھر آپ نے خود نرمی کے ساتھ اس سے دریافت
فرمایا کہ لشکر اس وقت کہاں ہے.اس نے جواب دیا اس سامنے والے ٹیلے کے پیچھے ہے.آپ نے
پوچھا کہ لشکر میں کتنے آدمی ہیں.اس نے جواب دیا کہ بہت ہیں مگر پوری پوری تعداد مجھے معلوم نہیں ہے.آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے لئے ہر روز کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں.اس نے کہا کہ دس ہوتے
ہیں.آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ ایک ہزار آدمی معلوم ہوتے ہیں ہے اور حقیقتاً وہ اتنے ہی
تھے.پھر آپ نے اس غلام سے پوچھا کہ رؤساء قریش میں سے کون کون لوگ ہیں.اس نے کہا.عتبہ،
شیبہ، ابوجہل، ابوالبختری ، عقبہ بن ابی معیط ، حکیم بن حزام ، نضر بن حارث، امیہ بن خلف سہیل بن
عمر و، نوفل بن خویلد، طعیمہ بن عدی ، زمعہ بن اسود وغیرہ وغیرہ سب ساتھ ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا هذَا مَكَّةَ قَدْ الْقَتْ إِلَيْكُمُ افَلا ذَ كَبِدِهَا.یعنی ”لو مکہ نے تمہارے
ابن ہشام
سے مسلم وابوداؤد
،،
: ابھی تک قافلہ کا خیال دل سے نہیں نکلا تھا اور اسی کی خواہش غالب تھی.: طبری صفحه ۱۳۸۹
ه مسلم وابوداؤد
Page 419
۴۰۴
،،،
سامنے اپنے جگر گوشے نکال کر ڈال دیئے ہیں.یہ نہایت دانشمندانہ اور حکیمانہ الفاظ تھے جو آپ کی
زبان مبارک سے بے ساختہ طور پر نکلے کیونکہ بجائے اس کے کہ قریش کے اتنے نامور رؤساء کا ذکر آنے
سے کمزور طبیعت مسلمان بے دل ہوتے ان الفاظ نے ان کی قوت متخیلہ کو اس طرف مائل کر دیا کہ گویا
ان سردارانِ قریش کو تو خدا نے مسلمانوں کا شکار بننے کے لئے بھیجا ہے.جس جگہ اسلامی لشکر نے ڈیرہ ڈالا تھا وہ کوئی ایسی اچھی جگہ نہ تھی.اس پر حباب بن منذر نے آپ سے
دریافت کیا کہ آیا خدائی الہام کے ماتحت آپ نے یہ جگہ پسند کی ہے یا محض فوجی تدبیر کے طور پر اسے اختیار
کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارہ میں کوئی خدائی حکم نہیں ہے تم کوئی مشورہ دینا
چاہتے ہو تو بتا ؤ ؟ حباب نے عرض کیا تو پھر میرے خیال میں یہ جگہ اچھی نہیں ہے.بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر
قریش سے قریب ترین چشمہ پر قبضہ کر لیا جاوے.میں اس چشمہ کو جانتا ہوں.اس کا پانی اچھا ہے
اور عموماً ہوتا بھی کافی ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فر مایا اور چونکہ ابھی تک قریش
ٹیلہ کے پرے ڈیرہ ڈالے پڑے تھے اور یہ چشمہ خالی تھا، مسلمان آگے بڑھ کر اس چشمہ پر قابض ہو گئے
یکن جیسا کہ قرآن شریف میں اشارہ پایا جاتا ہے اس وقت اس چشمہ میں بھی پانی زیادہ نہیں تھا
اور مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوتی تھی.پھر یہ بھی تھا کہ وادی کے جس طرف مسلمان تھے وہ ایسی
اچھی یہ تھی کیونکہ اس طرف ریت بہت تھی جس کی وجہ سے پاؤں اچھی طرح جمتے نہیں تھے.جگہ کے انتخاب کے بعد سعد بن معاذ رئیس اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصہ میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ایک سائبان سا تیار کر دیا اور سعد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سواری سائبان کے پاس باندھ کر عرض کیا کہ 'یا رسول اللہ ! آپ اس سائبان میں تشریف رکھیں اور ہم اللہ
کا نام لے کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں.اگر خدا نے ہمیں فتح دی تو یہی ہماری آرزو ہے لیکن اگر خدانخواستہ
معاملہ دگر گوں ہوا تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر جس طرح بھی ہو مدینہ پہنچ جائیں.وہاں ہمارے ایسے
بھائی بند موجود ہیں جو محبت و اخلاص میں ہم سے کم نہیں ہیں.لیکن چونکہ ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ اس مہم میں
جنگ پیش آجائے گی اس لئے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ورنہ ہرگز پیچھے نہ رہتے لیکن جب انہیں حالات
کا علم ہوگا ، تو وہ آپ کی حفاظت میں جان تک لڑا دینے سے دریغ نہیں کریں گے.یہ سعد کا جوشِ
،،
اخلاص تھا جو ہر حالت میں قابل تعریف ہے، ورنہ بھلا خدا کا رسول اور میدان سے بھاگے.چنانچہ حنین
ابن ہشام وطبری
: طبری وابن ہشام
Page 420
۴۰۵
کے میدان میں بارہ ہزار فوج نے پیٹھ دکھائی ،مگر یہ مرکز تو حید اپنی جگہ سے متزلزل نہیں ہوا.بہرحال
سائبان تیار کیا گیا اور سعد اور بعض دوسرے انصار اس کے گرد پہرہ دینے کے لئے کھڑے
ہو گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے اسی سائبان میں رات بسر کی.اور آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے رات بھر خدا کے حضور گریہ وزاری سے دعائیں کیں اور لکھا ہے کہ سارے لشکر میں صرف
آپ ہی تھے جو رات بھر جاگے ، باقی سب لوگ باری باری اپنی نیند سو لئے.اور چونکہ نیند کا آنا بھی ایک
اطمینان کی علامت سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا قرآن شریف میں ذکر کیا ہے.پھر خدا کا مزید
فضل یہ ہوا کہ کچھ بارش بھی ہوگئی جس سے مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا کہ حوض بنا بنا کر پانی جمع کر لیں.اور
یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ ریت حجم گئی اور پاؤں زمین میں دھسنے سے رک گئے.دوسری طرف قریش والی
جگہ میں کیچڑ کی سی صورت ہو گئی اور اس طرف کا پانی بھی کچھ گدلا ہو کر میلا ہو گیا.اس واقعہ کا بھی
قرآن شریف نے ذکر کیا ہے.اب رمضان ۲ ہجری کی سترہ تاریخ اور جمعہ کا دن تھا.اور عیسوی حساب سے ۱۴ / مارچ ۶۲۳ تھی.صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کی گئی اور پرستاران احدیت کھلے میدان میں خدائے واحد کے حضور
سر بسجو د ہوئے.اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ایک خطبہ فرمایا اور پھر جب ذرا روشنی
ہوئی تو آپ نے ایک تیر کے اشارہ سے مسلمانوں کی صفوں کو درست کرنا شروع کیا.ایک صحابی سواد نامی
صف سے کچھ آگے نکلا کھڑا تھا آپ نے اسے تیر کے اشارہ سے پیچھے ہٹنے کو کہا مگر اتفاق سے آپ کے تیر
کی لکڑی اس کے سینہ پر جا لگی.اس نے جرات کے انداز سے عرض کیا.”یا رسول اللہ! آپ کو خدا نے
حق وانصاف کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے.مگر آپ نے مجھے ناحق تیر مارا ہے واللہ میں تو اس کا بدلہ لوں
گا.صحابہ انگشت بدنداں تھے کہ سواد کو کیا ہو گیا ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے
فرمایا کہ اچھا سواد تم بھی مجھے تیر مار لو اور آپ نے اپنے سینہ سے کپڑا اٹھا دیا.سواد نے فرط محبت سے آگے
بڑھ کر آپ کا سینہ چوم لیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا.”سواد یہ تمہیں کیا
سوجھی.اس نے رقت بھری آواز میں عرض کیا.یا رسول اللہ ! دشمن سامنے ہے کچھ خبر نہیں کہ یہاں سے
بیچ کر جانا ملتا ہے یا نہیں.میں نے چاہا کہ شہادت سے پہلے آپ کے جسم مبارک سے اپنا جسم چھو جاؤں.“ ہے
لے ہر دو واقعات کے لئے دیکھوسورۃ انفال :
: توفیقات
۲۰ :
"
: ابن ہشام وابن سعد
ابن ہشام
Page 421
۴۰۶
غالباً اسی وقت کے قریب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حذیفہ بن یمان اور ابوجبل حاضر ہوئے
اور عرض کیا ہم ابھی ابھی مکہ سے آرہے ہیں.جب ہم وہاں سے نکلے تھے تو قریش نے ہم کو روک دیا
تھا اور پھر یہ عہد لے کر چھوڑا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہو کر ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے.گو یہ عہد
قابل ایفا نہیں تھا کیونکہ جبر آلیا گیا تھا مگر آپ نے فرمایا.تو پھر تم جاؤ اور اپنے عہد کو پورا کرو.ہم اللہ ہی
سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کی نصرت پر ہمارا بھروسہ ہے.1
ابھی آپ صفوں کی درستی میں ہی مصروف تھے کہ قریش کے لشکر میں حرکت پیدا ہوئی اور لشکر کفار
میدان قتال کی طرف بڑھنا شروع ہوا.یہ وہ موقع تھا جبکہ کفار کو مسلمان اصلی تعداد سے کم نظر آتے تھے.اس لئے وہ جرات کے ساتھ بڑھتے آئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا تو فرمایا
”اے میرے مولا! یہ لوگ تکبر و غرور سے بھرے ہوئے تیرے دین کے مٹانے کے لئے آئے ہیں تو اپنے
وعدہ کے مطابق اپنے دین کی نصرت فرما.اسی اثنا میں قریش کے چند آدمی مسلمانوں کے چشمہ کی
طرف بڑھے.صحابہ نے روکنا چاہا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حکم دیا کہ ان کو پانی پی
لینے دیا جاوے.چنانچہ انہوں نے امن کے ساتھ پانی پیا اور اپنے لشکر کو واپس لوٹ گئے ہے دشمن کے
ساتھ اس عدل واحسان کا معاملہ کرنا عرب کے ضابطہ اخلاق میں مفقود تھا اور یہ اسلام کی ایک خصوصیت
ہے کہ اس نے خود حفاظتی قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے دشمن سے بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے.اب فوجیں بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھیں مگر قدرت الہی کا عجیب تماشہ ہے کہ اس وقت
لشکروں کے کھڑے ہونے کی ترتیب ایسی تھی کہ اسلامی لشکر قریش کو اصلی تعداد سے زیادہ بلکہ دو گنا نظر آتا
تھا.جس کی وجہ سے کفار مرعوب ہوئے جاتے تھے اور دوسری طرف قریش کالشکر مسلمانوں کو ان کی اصلی
تعداد سے کم نظر آتا تھا.جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے دل بڑھے ہوئے تھے.قریش کی یہ کوشش تھی کہ
کسی طرح اسلامی لشکر کی تعداد کا صحیح اندازہ پتہ لگ جاوے تا کہ وہ چھوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دے
سکیں.اس کے لئے رؤساء قریش نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ اسلامی لشکر کے چاروں طرف گھوڑا دوڑا
کر دیکھے کہ اس کی تعداد کتنی ہے اور آیا ان کے پیچھے کوئی کمک تو مخفی نہیں؟ چنانچہ عمیر نے گھوڑے پر سوار
ہو کر مسلمانوں کا ایک چکر کاٹا مگر اسے مسلمانوں کی شکل وصورت سے ایسا جلال اور عزم اور موت سے ایسی
مسلم کتاب الجہاد باب الوفاء بالعهد ۲ : سورۃ انفال : ۴۵
: طبری وابن ہشام
ابن ہشام و طبری
۵ : سورة ال عمران : ۱۴ : سورۃ انفال : ۴۵
Page 422
۴۰۷
بے پروائی نظر آئی کہ وہ سخت مرعوب ہو کر لوٹا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا مَا رَأَيْتُ شَيْئًا وَلَكِنِّي
قَدْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ الْقُرَيْشِ اَلبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا نَوَاضِحُ يَثْرَبَ تَحْمِلُ الْمَوْتَ النَّاقِعَ -
یعنی ”مجھے کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نظر نہیں آئی لیکن اے معشر قریش! میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر
میں گو یا اونٹنیوں کے کجاووں نے اپنے اوپر آدمیوں
کو نہیں بلکہ موتوں کو اٹھایا ہوا ہے اور میٹر ب کی سانڈ نیوں
پر گویا ہلاکتیں سوار ہیں.قریش نے جب یہ بات سنی تو ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی.سراقہ جو ان کا
ضامن بن کر آیا تھا کچھ ایسا مرعوب ہوا کہ الٹے پاؤں بھاگ گیا.اور جب لوگوں نے اسے روکا تو کہنے لگا
اني ارى مَا لَا تَرَوْون : " مجھے جو کچھ نظر آرہا ہے وہ تم نہیں دیکھتے.حکیم بن حزام نے عمیر کی رائے
سنی تو گھبرایا ہوا عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہنے لگا.اے عتبہ اتم محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) سے آخر
عمر و حضرمی کا بدلہ ہی چاہتے ہو..وہ تمہارا حلیف تھا کیا ایسا نہیں ہوسکتا کہ تم اس کی طرف سے خون بہا ادا
کر دو اور قریش کو لے کر واپس لوٹ جاؤ اس میں ہمیشہ کے لئے تمہاری نیک نامی رہے گی.‘ عقبہ جو خود
گھبرایا ہوا تھا اور کیا چاہئے تھا جھٹ بولا.”ہاں ہاں میں راضی ہوں اور پھر حکیم! دیکھ تو یہ مسلمان اور ہم
آخر آپس میں رشتہ دار ہی تو ہیں.کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے اور باپ بیٹے پر تم ایسا
کرو کہ ابھی ابوالحکم ( یعنی ابو جہل) کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے یہ تجویز پیش کرو.اور ادھر عتبہ نے
خود اونٹ پر سوار ہو کر اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ رشتہ داروں میں لڑائی ٹھیک نہیں
ہے.ہمیں واپس لوٹ جانا چاہئے اور محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہئے کہ وہ دوسرے قبائل عرب کے
ساتھ نپٹتا رہے جو نتیجہ ہو گا دیکھا جائے گا.اور پھر تم دیکھو کہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھی کوئی آسان
کام نہیں ہے کیونکہ خواہ تم مجھے بزدل کہو حالانکہ میں بزدل نہیں ہوں اِنّى أَرَى قَوْمًا مُسْتَمِيتِينَ.یعنی ” مجھے تو یہ لوگ موت کے خریدار نظر آتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عتبہ کو دیکھا تو
فرمایا.اگر لشکر کفار میں سے کسی میں شرافت ہے تو اس سرخ اونٹ کے سوار میں ضرور ہے.اگر یہ لوگ اس
کی بات مان لیں تو ان کے لئے اچھا ہو.لیکن جب حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے یہ تجویز
بیان کی تو وہ فرعون امت بھلا ایسی باتوں میں کب آنے والا تھا چھٹتے ہی بولا.اچھا اچھا اب عتبہ
: طبری وابن سعد وابن ہشام
یہ ایک پردہ رکھنے کی بات تھی ورنہ دل میں رؤساء قریش خوب جانتے تھے کہ عمرو کے قتل کا تو صرف ایک بہانہ ہے
ور نہ اصلی جلن اسلام کے نام کی ہے.: سورۃ انفال : ۴۹
: ابن ہشام وطبری ۵ : طبری
Page 423
۴۰۸
166
کو اپنے سامنے اپنے رشتہ دار نظر آنے لگے ہیں.اور پھر اس نے عمر وحضرمی کے بھائی عامر حضر می کو بلا کر
کہا ” تم نے سنا تمہارا حلیف عتبہ کیا کہتا ہے اور وہ بھی اس وقت جبکہ تمہارے بھائی کا بدلہ گو یا ہاتھ میں آیا
ہوا ہے.عامر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ
کر اور ننگا ہو کر چلانا
شروع کیا ” واعمراہ واعمراہ ہائے افسوس! میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے.ہائے
افسوس! میرا بھائی بغیر انتقام کے رہا جاتا ہے !! اس صحرائی آواز نے لشکر قریش کے سینوں میں عداوت کے
شعلے بلند کر دیئے اور جنگ کی بھٹی اپنے پورے زور سے دہکنے لگ گئی.1
ابوجہل کے طعنے نے عتبہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی.اس غصہ میں بھرا ہوا وہ اپنے بھائی شیبہ
اور اپنے لڑکے ولید کو ساتھ لے کر لشکر کفار سے آگے بڑھا اور عرب کے قدیم دستور کے مطابق انفرادی لڑائی
کے لئے مبارزطلبی کی.چند انصار ان کے مقابلہ کے لئے آگے بڑھنے لگے.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو روک دیا اور فرمایا.حمزہ تم اٹھو علی تم اٹھو ، عبیدہ تم اٹھو! یہ تینوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
نہایت قریبی رشتہ دار تھے اور آپ چاہتے تھے کہ خطرہ کی جگہ پر سب سے پہلے آپ کے عزیز واقارب آگے
بڑھیں.دوسری طرف عقبہ وغیرہ نے بھی انصار کو دیکھ کر آواز دی کہ ان لوگوں کو ہم کیا جانتے ہیں.ہماری
ٹکر کے ہمارے سامنے آئیں.چنانچہ حمزہ اور علی اور عبیدہ آگے بڑھے.عرب کے دستور کے مطابق پہلے
روشناسی ہوئی.پھر عبیدۃ بن مطلب ولید کے مقابل ہو گئے اور حمزہ عتبہ کے اور علی شیبہ کے تے حمزہ اور علی
نے تو ایک دوواروں میں ہی اپنے حریفوں کو خاک میں ملا دیا، لیکن عبیدۃ اور ولید میں دو چار ا چھی ضر ہیں
ہوئیں.اور بالآخر دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ سے کاری زخم کھا کر گرے.جس پر حمزہ اور علی نے جلدی
سے آگے بڑھ کر ولید کا تو خاتمہ کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے.مگر عبیدہ اس صدمہ سے
جانبر نہ ہو سکے اور بدر سے واپسی پر راستہ میں انتقال کیا.ان انفرادی مقابلوں کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے سائبان میں تشریف لے گئے
اور جاتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ جب تک میں حکم نہ دوں عام دھاوا نہ کیا جائے اور فرمایا کہ اگر کفار فوری
حملہ کر کے آئیں تو پہلے تیروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو لیکن دیکھو تیر ذرا احتیاط سے چلانا.ایسانہ ہو کہ
یونہی بے فائدہ طور پر اپنے ترکش خالی کردو اور تلوار صرف اس وقت نکالو کہ جب دونوں لشکر آپس میں مل
جائیں.غالباً اسی موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی فرمایا کہ لشکر کفار میں
ل ابن ہشام
ابوداؤد
Page 424
۴۰۹
بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے دل کی خوشی سے اس مہم میں شامل نہیں ہوئے بلکہ رؤساء قریش کے
دباؤ کی وجہ سے شامل ہو گئے ہیں.ورنہ وہ دل میں ہمارے مخالف نہیں.اسی طرح بعض ایسے لوگ بھی اس
لشکر میں شامل ہیں جنہوں نے مکہ میں ہماری مصیبت کے وقت میں ہم سے شریفانہ سلوک کیا تھا اور ہمارا
فرض ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ اتاریں.پس اگر کسی ایسے شخص پر کوئی مسلمان غلبہ پائے تو اسے کسی قسم کی
تکلیف نہ پہنچائے.اور آپ نے خصوصیت کے ساتھ قسم اول میں عباس بن عبدالمطلب اور قسم ثانی میں
ابوالبختری کا نام لیا اور ان کے قتل سے منع فرمایا.مگر حالات نے کچھ ایسی ناگزیر صورت اختیار کی کہ
ابوالبختری قتل سے بچ نہ سکا گوا سے مرنے سے قبل اس بات
کا علم ہو گیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کے قتل سے منع فرمایا ہے.اس کے بعد آپ سائبان میں جا کر پھر دعا میں مشغول ہو گئے.حضرت
ابوبکر بھی ساتھ تھے اور سائبان کے اردگرد انصار کی ایک جماعت سعد بن معاذ کی زیر کمان پہرہ پر متعین
تھی.تھوڑی دیر کے بعد میدان میں سے ایک شور بلند ہوا اور معلوم ہوا کہ قریش کے لشکر نے عام حملہ کر دیا
ہے.اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رفت کی حالت میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے
دعائیں کر رہے تھے اور نہایت اضطراب کی حالت میں فرماتے تھے کہ اللَّهُمَّ إِنِّي انْشُدُكَ عَهْدَكَ
وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِنْ اَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ اے
میرے خدا اپنے وعدوں کو پورا کر.اے میرے مالک ! اگر مسلمانوں کی یہ جماعت آج اس میدان میں
ہلاک ہوگئی تو دنیا میں تجھے پوجنے والا کوئی نہیں رہے گا.اور اس وقت آپ اس قدر کرب کی حالت میں
تھے کہ کبھی آپ سجدہ میں گر جاتے تھے اور کبھی کھڑے ہو کر خدا کو پکارتے تھے اور آپ کی چادر آپ کے
کندھوں سے گر گر پڑتی تھی اور حضرت ابو بکر اسے اٹھا اٹھا کر آپ پر ڈال دیتے تھے..حضرت علی کہتے
ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تھا تو میں آپ کے سائبان کی طرف
بھاگ جاتا تھا، لیکن جب بھی میں گیا میں نے آپ کو سجدہ میں گڑ گڑاتے ہوئے پایا.اور میں نے سنا کہ آپ
کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ہے یعنی ”اے میرے زندہ خدا ! اے
میرے زندگی بخش آقا! حضرت ابوبکر آپ کی اس حالت کو دیکھ کر بے چین ہوئے جاتے تھے اور کبھی کبھی
بے ساختہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں.آپ گھبرائیں نہیں.اللہ
طبری
مسلم وترندی
،،
بخاری و مسلم
نسائی وابن سعد
Page 425
۴۱۰
،،
اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا.مگر اس بچے مقولہ کے مطابق کہ ہر کہ عارف تر است ترساں تر.“
آپ برابر دعا اور گریہ وزاری میں مصروف رہے.دوسری طرف جب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بھڑ گئیں تو ابو جہل رئیس قریش نے بھی یوں دعا
کی کہ ” اے خدا! وہ فریق جس نے رشتوں کو توڑ رکھا ہے اور دین میں ایک بدعت پیدا کی ہے تو آج
اسے اس میدان میں تباہ و برباد کر.ایک دوسری روایت کے میں آتا ہے کہ اس موقع پر یا اس سے قبل
ابو جہل نے یہ دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب اگر محمد کا لایا ہوا دین سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی
بارش برسا یا کسی اور درد ناک عذاب سے ہمیں تباہ و برباد کر ۴
اب میدان کارزار میں کشت وخون کا میدان گرم تھا.مسلمانوں کے سامنے ان سے سہ چند جماعت
تھی جو ہر قسم کے سامان حرب سے آراستہ ہو کر اس عزم کے ساتھ میدان میں نکلی تھی کہ اسلام کا نام ونشان
مٹا دیا جاوے.اور مسلمان بیچارے تعداد میں تھوڑے، سامان میں تھوڑے، غربت اور بے وطنی کے
صدمات کے مارے ہوئے ظاہری اسباب کے لحاظ سے اہل مکہ کے سامنے چند منٹوں کا شکار تھے، مگر توحید
اور رسالت کی محبت نے انہیں متوالا بنا رکھا تھا اور اس چیز نے جس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی چیز نہیں
یعنی زندہ ایمان نے ان کے اندر ایک فوق العادت طاقت بھر دی تھی.وہ اس وقت میدانِ جنگ میں
خدمت دین کا وہ نمونہ دکھا رہے تھے جس کی نظیر نہیں ملتی.ہر اک شخص دوسرے سے بڑھ کر قدم مارتا تھا
اور خدا کی راہ میں جان دینے کے لئے بے قرار نظر آتا تھا.حمزہ اور علی اور زبیر نے دشمن کی صفوں کی صفیں
کاٹ کر رکھ دیں.انصار کے جوشِ اخلاص کا یہ عالم تھا کہ عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ جب
عام جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی.مگر کیا دیکھتا ہوں کہ انصار کے دونو جوان
لڑکے میرے پہلو بہ پہلو کھڑے ہیں.انہیں دیکھ کر میرا دل کچھ بیٹھ سا گیا کیونکہ ایسے جنگوں میں دائیں
بائیں کے ساتھیوں پر لڑائی کا بہت انحصار ہوتا تھا اور وہی شخص اچھی طرح لڑ سکتا ہے جس کے پہلو محفوظ
ہوں.مگر عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں اس خیال میں ہی تھا کہ ان لڑکوں میں سے ایک نے مجھ سے آہستہ سے
پوچھا کہ گویا وہ دوسرے سے اپنی یہ بات مخفی رکھنا چاہتا ہے کہ چا وہ ابو جہل کہاں ہے جو مکہ میں
ابن ہشام
: بخاری تفسیر سورۃ انفال
ے مسلم
: ابو جہل کی یہ دعا ئیں بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس مہم میں رؤساء قریش کا اصل مقصد اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا
تھا اور عمر وحضرمی کے قتل کا انتقام وغیرہ ایک محض بہانہ اور عامتہ الکفار کو جوش دلانے کا آلہ تھا.
Page 426
۴۱۱
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا میں نے خدا سے عہد کیا ہوا ہے کہ میں اسے قتل کروں
گا یا قتل
کرنے کی کوشش میں مارا جاؤں گا.میں نے ابھی اس کا جواب نہ دیا تھا کہ دوسری طرف سے دوسرے نے
بھی اسی طرح آہستہ سے یہی سوال کیا.میں ان کی یہ جرات دیکھ کر حیران سا رہ گیا.کیونکہ ابوجہل گویا
سردا را شکر تھا اور اس کے چاروں طرف آزمودہ کا رسپاہی جمع تھے.میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ
ابو جہل ہے.عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میرا اشارہ کرنا تھا کہ وہ دونوں بچے باز کی طرح جھپٹے اور دشمن کی صفیں
کاٹتے ہوئے ایک آن کی آن میں وہاں پہنچ گئے اور اس تیزی سے وار کیا کہ ابوجہل اور اس کے ساتھی
دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے اور ابو جہل خاک پر تھالے عکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے باپ کے ساتھ تھا.وہ اپنے
باپ کو تو نہ بچا سکا مگر اس نے پیچھے سے معاذ پر ایسا وار کیا کہ ان کا بایاں بازو کٹ کر لٹکنے لگ گیا.معاذ نے
عکرمہ کا پیچھا کیا مگر وہ بیچ کر نکل گیا.چونکہ کٹا ہوا باز ولڑنے میں مزاحم ہوتا تھا.معاذ نے اسے زور کے
ساتھ کھینچ کر اپنے جسم سے الگ کر دیا اور پھر لڑنے لگ گئے.یہ غرض کیا مہاجر اور کیا انصار سب مسلمان
پورے زور وشور اور اخلاص کے ساتھ لڑے مگر دشمن کی کثرت اور اس کے سامان کی زیادتی کچھ پیش نہ
جانے دیتی تھی اور نتیجہ ایک عرصہ تک مشتبہ رہا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر دعا وابتہال میں مصروف تھے
اور آپ کا اضطراب لحظہ بہ لحظہ بڑھتا جاتا تھا مگر آخر ایک کافی لمبے عرصے کے بعد آپ سجدہ سے اٹھے اور
066
خدائی بشارت سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ.کہتے ہوئے سائبان سے باہر نکل آئے..باہر آکر آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کشت و خون کا میدان گرم پایا.اس وقت آپ نے
ریت اور کنکر کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسے کفار کی طرف پھینکا.اور جوش کے ساتھ فرمایا شَاهَتِ الْوُجُوهُ
دشمنوں کے منہ بگڑ جائیں.اور ساتھ ہی آپ نے مسلمانوں سے پکار کر فرمایا یکدم حملہ کرو.مسلمانوں کے کانوں میں اپنے محبوب آقا کی آواز پہنچی اور انہوں نے تکبیر کا نعرہ لگا کر یکدم حملہ
کر دیا.دوسری طرف ادھر آپ کا مٹھی بھر کر ریت پھینکنا تھا کہ ایسی آندھی کا جھونکا آیا کہ کفار کی آنکھیں
بخاری کتاب المغازی
یعنی لشکر کفار ضرور پسپا ہوگا اور پیٹھ دکھائے گا.یہ قرآن کریم سورۃ قمر کی آیت ۴۶ ہے جو کہ مکہ میں ہجرت
طبری
سے پہلے بطور پیشگوئی کے نازل ہوئی تھی اور اب خدا نے اسے آپ کی زبان پر دوبارہ جاری کر کے بتایا کہ کفار مکہ کے لئے
اب وہی موعود ساعت آگئی.ه: طبری و زرقانی
: سورۃ انفال :
طبری
۱۸ :
Page 427
۴۱۲
اور منہ اور ناک ریت اور کنکر سے بھرنے شروع ہو گئے یا آپ نے فرمایا.یہ خدائی فرشتوں کی فوج ہے جو
ہماری نصرت کو آئی ہے اور روایتوں میں مذکور ہے کہ اس وقت بعض لوگوں کو یہ فرشتے نظر بھی
آئے.بہر حال عتبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے رؤساء قریش تو خاک میں مل ہی چکے تھے.مسلمانوں کے اس
فوری دھاوے اور آندھی کے اچانک جھونکے کے نتیجہ میں قریش کے پاؤں اکھڑ نے شروع ہو گئے اور جلد
ہی کفار کے لشکر میں بھا گڑ پڑ گئی اور تھوڑی دیر میں میدان صاف تھا.مسلمانوں نے ستر قیدی پکڑے اور
جب لڑائی کے بعد مقتولین کی دیکھ بھال کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہی تعداد قریش کے مقتولین کی تھی اور جب
مقتولین کی شناخت ہوئی تو قرآنی آیت وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِینَ کی ہیبت ناک تفسیر آنکھوں کے
سامنے تھی یعنی تمام بڑے بڑے رؤساء قریش خاک میں ملے پڑے تھے اور جو ایک دور کیس بچے تھے وہ
مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی تھے.البتہ شروع شروع میں ابو جہل کی لاش نظر نہ آتی تھی.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جا کر اچھی طرح دیکھے کہ ابو جہل کا کیا حال ہے.عبداللہ بن مسعود گئے اور
دیکھ بھال کے بعد اسے ایک جگہ جان توڑتے ہوئے پایا جبکہ وہ قریباً ٹھنڈا ہو چکا تھا.عبداللہ نے اس سے
پوچھا تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا هَلُ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ کیا تم نے مجھ سے بھی کوئی بڑا شخص قتل کیا
ہے؟ یعنی میں سب سے بڑا آدمی ہوں جو تم نے مارا ہے.پھر کہنے لگا لَوْ غَيْرَ اكَارِ قَتَلَنِی
کاش میں کسی کسان کے ہاتھ سے قتل نہ ہوتا ہے پھر اس نے پوچھا کہ میدان کس کے ہاتھ میں رہا ہے؟
عبداللہ نے جواب دیا خدا اور اس کے رسول کے ہاتھ.اس کے بعد ابو جہل بالکل بے حس وحرکت ہو گیا
اور جان دے دی.اور عبد اللہ بن مسعود نے واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قتل کی اطلاع
دی.امیہ بن خلف جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی وجہ سے مکہ سے نہیں نکلتا تھا مگر جس کا دل
عداوت اسلام اور بغض رسول سے بھرا ہوا تھا اس کا انجام یوں ہوا کہ جس وقت لشکر قریش پسپا ہوا اس نے
اپنے جاہلیت کے دوست عبدالرحمن بن عوف کے پاس پناہ ڈھونڈی جن کا اس کے ساتھ یہ معاہدہ تھا کہ
وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے لیکن جو نہی کہ بلال کی نظر امیہ پر پڑی اس نے شور مچا دیا کہ دیکھو
یہ راس الکفر بیچ کر نکلا جا رہا ہے، جس پر چند انصاریوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے ساتھ لڑ کر اسے مار
زرقانی
ے بخاری
،،
: یعنی خدا نے یہ لڑائی اس لئے کرائی تھی کہ کفار کی جڑ کاٹ دی جاوے.انفال: ۸
یہ اس نے اس لئے کہا کہ اہل مکہ چونکہ زراعت کو برا سمجھتے تھے اس لئے بعض اوقات
زرقانی جلد اصفحه ۴۲۸ بحوالہ ابن عقبہ
مدینہ کے لوگوں کو تحقیر کے لہجہ میں کسان کہا کرتے تھے
Page 428
۴۱۳
کر گرادیا بلکہ اسے بچاتے بچاتے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی کسی قدر زخمی ہو گئے ہے
جب دوسرے کاموں سے فراغت حاصل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
رؤساء قریش کو ایک جگہ جمع کر کے دفن کر دیا جاوے.چنانچہ ایک گڑھے میں چوبیس رؤساء کی لاشوں کو
اکٹھا کر کے دفنا دیا گیا اور دوسرے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر دفن کر دیا گیا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ عام طریق تھا کہ حتی الوسع کسی لاش کو کھلا نہیں رہنے دیتے تھے خواہ وہ دشمن ہی کی کیوں نہ ہو نے واپسی
سے قبل آپ اس گڑھے کے پاس تشریف لے گئے جس میں رؤساء قریش دفن کئے گئے تھے اور پھر ان میں
سے ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فرمایا هَلُ وَجَدْتُمُ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ حَقَّافَاتِي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيَ
اللهُ حَقًّا.یعنی ” کیا تم نے اس وعدہ کو حق پایا جو خدا نے میرے ذریعہ تم سے کیا تھا.تحقیق میں نے اس
وعدہ کو حق پالیا ہے جو خدا نے مجھ سے کیا تھا.نیز فرمایا یا اَهلَ الْقَلِيبِ بِئْسَ عَشِيْرَةُ النَّبِيِّ كُنتُمْ
لِنَبِيِّكُمْ كَذَّبْتُمُونِي وَصَدَقَنِيَ النَّاسُ وَاَخْرَجْتُمُونِي وَآوَانِيَ النَّاسُ وَقَاتَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِي
النَّاسُ ہے یعنی اے گڑھے میں پڑے ہوئے لوگو! تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار بنے.تم نے مجھے
جھٹلایا اور دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی.تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا اور دوسروں نے مجھے پناہ
دی.تم نے میرے خلاف جنگ کی.اور دوسروں نے میری مدد کی.“ حضرت عمرؓ نے عرض کیا.یا رسول
اللہ ! وہ اب مردہ ہیں وہ کیا سنیں گے.آپ نے فرمایا.” میری یہ بات وہ تم سے بھی بہترسن رہے ہیں.“
یعنی وہ اس عالم میں پہنچ چکے ہیں جہاں ساری حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے اور کوئی پردہ نہیں رہتا.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات جوا و پر درج کئے گئے ہیں اپنے اندر ایک عجیب درد و الم کی آمیزش رکھتے ہیں
اور ان سے اس قلبی کیفیت کا کچھ تھوڑ اسا اندازہ ہو سکتا ہے جواس وقت آپ پر طاری تھی.ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ اس وقت قریش کی مخالفت کی گزشتہ تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھی اور آپ عالم تخیل میں
اس کا ایک ایک ورق الٹاتے جاتے تھے اور آپ کا دل ان اوراق کے مطالعہ سے بے چین تھا.آپ کے
یہ الفاظ اس بات کا بھی یقینی ثبوت ہیں کہ اس سلسلہ جنگ کے آغاز کی ذمہ داری کلیۂ کفار مکہ پر تھی.جیسا
کہ آپ کے الفاظ قَاتَلْتُمُونِي وَنَصَرَنِي النَّاسُ سے ظاہر ہے.یعنی ”اے میری قوم کے لوگو! تم نے
مجھ سے جنگ کی اور دوسروں نے میری مدد کی.اور کم از کم ان الفاظ سے یہ تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ
بخاری کتاب الوکالۃ
سے بخاری کتاب المغازی
: دارقطنی بحوالہ روض الانف
طبری صفحه ۱۳۳۲
Page 429
۴۱۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ یہی یقین رکھتے تھے کہ ان جنگوں میں ابتدا کفار کی طرف سے ہوئی ہے
اور آپ نے مجبور ہو کر محض خود حفاظتی میں تلوار اٹھائی ہے.اپنے مقتولین کی دیکھ بھال ہوئی تو معلوم ہوا کہ کل چودہ آدمی شہید ہوئے ہیں.جن میں سے چھ
مہاجرین میں سے تھے اور باقی انصار تھے.انہیں میں وہ مخلص بچہ عمیر وقاص بھی تھا، جس نے روکر ساتھ
آنے کی اجازت حاصل کی تھی.اس کے علاوہ زخمی تو بہت سے صحابہ ہوئے تھے لیکن یہ نقصان ایسا نہیں تھا
کہ اس عظیم الشان دینی فتح کی خوشی کو مکدر کر سکتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ مسلمان شکر وامتنان
کے جذبات سے معمور تھے.تین دن تک آپ نے بدر کی وادی میں قیام فرمایا.اور یہ وقت اپنے شہداء کی
متخلفین و تد فین اور اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی میں گزرا.اور انہی دنوں میں غنیمت کے اموال کو جمع کر کے
مرتب کیا گیا اور کفار کے قیدیوں کو جن کی تعدا دست تھی محفوظ کر کے مختلف مسلمانوں کی سپردگی میں دے دیا
گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ قیدیوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک
کریں اور ان کے آرام کا خیال رکھیں.صحابہ نے جن کو اپنے آقا کی ہر خواہش کے پورا کرنے کا عشق
تھا آپ کی اس نصیحت پر اس خوبی کے ساتھ عمل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس
کی نظیر نہیں ملتی.چنانچہ خودان
قیدیوں میں سے ایک قیدی ابوعزیز بن عمیر کی زبانی روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی
وجہ سے انصار مجھے تو پکی ہوئی روٹی دیتے تھے لیکن خود کھجور وغیرہ کھا کر گزارہ کر لیتے تھے اور کئی دفعہ ایسا
ہوتا تھا کہ ان کے پاس اگر روٹی کا چھوٹا ٹکڑا بھی ہوتا تھا تو وہ مجھے دے دیتے تھے اور خود نہیں کھاتے
تھے اور اگر میں کبھی شرم کی وجہ سے واپس کر دیتا تھا تو وہ اصرار کے ساتھ پھر مجھی کو دے دیتے تھے.جن قیدیوں کے پاس لباس کافی نہیں تھا انہیں کپڑے مہیا کر دئیے گئے تھے.چنانچہ عباس کو عبداللہ بن ابی
نے اپنی قمیص دی تھی.ہے
سرولیم میور نے قیدیوں کے ساتھ اس مشفقانہ سلوک کا مندرجہ ذیل الفاظ میں اعتراف کیا ہے.محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہدایت کے ماتحت انصار و مہاجرین نے کفار کے قیدیوں
کے ساتھ بڑی محبت اور مہربانی کا سلوک کیا.چنانچہ بعض قیدیوں کی اپنی شہادت تاریخ میں
ان الفاظ میں مذکور ہے کہ ”خدا بھلا کرے مدینہ والوں کا وہ ہم کو سوار کرتے تھے اور آپ
پیدل چلتے تھے.ہم کو گندم کی پکی ہوئی روٹی دیتے تھے اور آپ صرف کھجوریں کھا کر پڑرہتے تھے.طبری وابن ہشام حالات غزوہ بدر
بخاری
Page 430
۴۱۵
اس لئے ( میور صاحب لکھتے ہیں ) ہم کو یہ معلوم کر کے تعجب نہ کرنا چاہئے کہ بعض قیدی اس نیک
سلوک کے اثر کے نیچے مسلمان ہو گئے اور ایسے لوگوں کو فوراً آزاد کر دیا گیا....جو قیدی اسلام
نہیں لائے ان پر بھی اس نیک سلوک کا بہت اچھا اثر تھا.“
یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب یہ قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کئے گئے تو آپ نے
فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ سے ان لوگوں کی سفارش کرتا تو میں ان کو یونہی چھوڑ
دیتا.مطعم پکا مشرک تھا اور اسی حالت میں وہ مرا لیکن طبیعت میں شرافت کا مادہ رکھتا تھا.چنانچہ قریش کا
ظالمانہ صحیفہ جس کی وجہ سے مسلمان شعب ابی طالب میں محصور کر دیئے گئے تھے اسے مطعم نے ہی چاک کیا
تھا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے تو اس وقت بھی مطعم نے ہی
آپ کو اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں داخل کیا تھا.یہ اسی احسان کی یاد تھی جس سے متاثر ہو کر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے.دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک نمایاں خصوصیت تھی کہ
جب کبھی کوئی شخص آپ کے ساتھ ذرا سا بھی نیک سلوک کرتا تھا تو آپ اس کے احسان کو کبھی نہیں بھولتے تھے
اور آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ آپ کو اس کے احسان کا عملی شکر یہ ادا کر نے کا موقع ملتار ہے اور یہ
نہیں تھا کہ دنیا داروں کی طرح جب آپ ایک دفعہ کسی کے احسان کے جواب میں نیک سلوک کر لیتے تھے
تو پھر یہ کہنے لگ جاتے تھے کہ بس اب احسان
کا بدلہ اتر گیا ہے بلکہ جب کبھی کوئی شخص آپ کے ساتھ
نیک سلوک کرتا تھا تو پھر وہ ہمیشہ کے لئے آپ کو اپنا خاص محسن بنالیتا تھا اور آپ کبھی بھی اس کے احسان
کو اترا ہوا نہیں سمجھتے تھے اور دراصل اعلیٰ اخلاق کا یہی تقاضا ہے کیونکہ جس احسان کے نیچے انسان ایک
دفعہ آ جاوے پھر اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ کسی جوابی احسان سے اس کا بدلہ اتر سکتا ہے ایک تجارتی لین دین
تو کہلا سکتا ہے مگر ایک اخلاقی ذمہ داری سے عہدہ برآئی ہرگز نہیں سمجھا جاسکتا.جولوگ قید ہوئے تھے ان میں سے بعض رؤساء قریش میں سے تھے.چنانچہ النضر بن الحارث اور
سہیل بن عمر ومکہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے.بعض قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت
قریبی رشتہ دار تھے مثلاً عباس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے.عقیل آپ کے چچازاد بھائی اور
حضرت علی کے حقیقی بھائی تھے.ابو العاص بن ربیع تھے جو آپ کی صاحبزادی زینب کے خاوند یعنی آپ کے
داماد تھے.بعض مورخین نے قید ہونے والے رؤساء میں عقبہ بن ابی معیط کا نام بھی بیان کیا ہے اور لکھا ہے
: مطعم مکہ کا ایک رئیس تھا جو کفر کی حالت میں مرگیا تھا
: بخاری کتاب المغازی
Page 431
۴۱۶
کہ وہ بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت حالت قید میں قتل کر دیا گیا تھا.مگر یہ درست
نہیں ہے.حدیث اور تاریخ میں نہایت صراحت کے ساتھ یہ روایت آتی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط
میدان جنگ میں قتل ہوا تھا اور ان رؤساء مکہ میں سے تھا جن کی لاشیں ایک گڑھے میں دفن کی گئی
تھیں.البتہ نضر بن حارث کا حالت قید میں قتل کیا جانا اکثر روایات سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کے قتل کی وجہ
یہ تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ان بے گناہ مسلمانوں کے قتل کے براہ راست ذمہ دار تھے جو مکہ میں
کفار کے ہاتھ سے مارے گئے تھے.اور اغلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حارث بن
ابی ہالہ جوابتدا اسلام میں نہایت ظالمانہ طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے قتل کئے
گئے تھے.ان کے قتل کرنے والوں میں نضر بن حارث بھی شامل تھا.لیکن یہ یقینی ہے کہ نضر کے سوا کوئی
قیدی قتل نہیں کیا گیا اور نہ ہی اسلام میں صرف دشمن ہونے اور جنگ میں خلاف حصہ لینے کی وجہ سے
قیدیوں کے قتل کرنے کا دستور تھا.چنانچہ اس کے متعلق بعد میں ایک معین حکم بھی قرآن شریف میں نازل
ہوا.یہ بھی یادرکھنا چاہئے کہ گو بہت سی روایات میں نضر بن حارث کے قتل کئے جانے کا ذکر آتا ہے لیکن
بعض ایسی روایتیں بھی پائی جاتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ بدر کے بعد مدت
تک زندہ رہا اور بالآخر غزوہ حنین کے موقع پر مسلمان ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں
شامل ہو گیا تھا.مگر مقدم الذکر روایات کے مقابلہ میں یہ روایتیں عموماً کمزور سمجھی گئیں ہیں.واللہ اعلم.بہر حال اگر قیدیوں میں سے کوئی شخص قتل کیا گیا تو وہ صرف نضر بن حارث تھا جو قصاص میں
قتل کیا گیا
تھا اور اس کے متعلق بھی یہ روایت آتی ہے کہ جب اس کے قتل کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کی بہن کے وہ دردناک اشعار سنے جن میں آپ سے رحم کی اپیل کی گئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ
اشعار مجھے پہلے پہنچ جاتے تو میں نفر کو معاف کر دیتا.بہر حال نضر کے سوا کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا
بلکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ
بہت اچھا سلوک کیا جاوے.بدر سے روانہ ہوتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مدینہ کی طرف روانہ فرمایا
ل : بخاری کتاب الوضوء و كتاب سترة المصلى و کتاب الجہاد ہے : ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۱۵
: اصابه ذکر حارث
سورة محمد : ۵ نیز دیکھو کتاب الخراج صفحه ۱۲۱
زرقانی حالات غزوہ بدر اور اسد الغابہ ذکر نضر بن حارث : ابن ہشام
Page 432
۴۱۷
تا کہ وہ آگے آگے جا کر اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری پہنچا دیں.چنانچہ انہوں نے آپ سے پہلے پہنچ کر مدینہ
والوں کو فتح کی خبر پہنچائی.جس سے مدینہ کے صحابہ کو اگر ایک طرف اسلام کی عظیم الشان فتح ہونے کے لحاظ
سے کمال درجہ خوشی ہوئی تو اس لحاظ سے کسی قدر افسوس بھی ہوا کہ اس عظیم الشان جہاد کے ثواب سے وہ خود
محروم رہے.اس خوشخبری نے اس غم کو بھی غلط کر دیا جو زید بن حارثہ کی آمد سے تھوڑی دیر قبیل مسلمانان مدینہ
کو عموماً اور حضرت عثمان کو خصوصاً رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہنچا تھا جن کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بیمار چھوڑ کر غزوہ بدر کے لئے تشریف لے گئے تھے اور جن کی وجہ سے
حضرت عثمان بھی شریک غز وہ نہیں ہو سکے.مدینہ پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا کرنا چاہئے.عرب میں بالعموم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا دستور تھا.مگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی.اور پھر ابھی تک اس بارہ میں کوئی الہی احکام بھی
نازل نہیں ہوئے تھے.حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میری رائے میں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا
چاہئے.کیونکہ آخر یہ لوگ اپنے ہی بھائی بند ہیں اور کیا تعجب کہ کل کو انہی میں سے فدایانِ اسلام پیدا
ہو جائیں.مگر حضرت عمر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ دین کے معاملہ میں رشتہ داری کا کوئی پاس
نہیں ہونا چاہئے اور یہ لوگ اپنے افعال سے قتل کے مستحق ہو چکے ہیں.پس میری رائے میں ان سب کو قتل
کر دینا چاہئے بلکہ حکم دیا جاوے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھ سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل
کریں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری رحم سے متاثر ہو کر حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند
فرمایا اور قتل کے خلاف فیصلہ کیا اور حکم دیا کہ جو مشرکین اپنا فدیہ وغیرہ ادا کر دیں انہیں چھوڑ دیا جاوے لے
چنانچہ بعد میں اس کے مطابق الہی حکم نازل ہوا.چنانچہ ہر شخص کے مناسب حال ایک ہزار درہم سے لے
کر چار ہزار درہم تک اس کا فدیہ مقرر کر دیا گیا.اس طرح سارے قیدی رہا ہوتے گئے.عباس جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے اور ان کو آپ سے اور آپ کو ان سے بہت محبت تھی ان کے
متعلق انصار نے عرض کیا کہ یہ ہمارا بھانجا ہے.یہ ہم انہیں بغیر فدیہ کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن گو قیدی کو بطور
احسان کے چھوڑ دینا اسلام میں جائز بلکہ پسندیدہ تھا مگر اس موقع پر عباس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
لے مسلم کتاب الجہاد.ترندی تفسیر سورۃ انفال و زرقانی جلد اصفحه ۴۴۰ - ۴۴۱ ۲ : سورة محمد و کتاب الخراج صفحه ۱۲۱
یاد ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑدادی مدینہ کی تھیں.: ابن سعد
Page 433
۴۱۸
نے نہیں مانا اور فرمایا کہ عباس فدیہ ادا کریں تو تب چھوڑے جائیں یا عباس کے متعلق یہ بھی روایت
آتی ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں بندھے ہوئے پڑے تھے تو رات کے وقت ان کے کراہنے کی وجہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی تھی.انصار کو معلوم ہوا تو انہوں نے عباس کے بندھن ڈھیلے
کر دئیے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر بندھن ڈھیلے کرتے ہو تو
سب کے کرو.عباس کی کوئی خصوصیت نہیں.چنانچہ سارے قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دئیے
گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داما دا بو العاص بھی اسیران بدر میں سے تھے.ان کے فدیہ میں ان کی
زوجہ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب نے جو ابھی تک مکہ میں تھیں کچھ چیزیں بھیجیں.ان میں ان کا ایک ہار بھی تھا.یہ ہار وہ تھا جو حضرت خدیجہ نے جہیز میں اپنی لڑکی زینب کو دیا تھا.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو مرحومہ خدیجہ کی یاد دل میں تازہ ہوگئی اور آپ چشم پر آب ہو گئے
اور صحابہ سے فرمایا اگر تم پسند کرو تو زینب کا مال اسے واپس کر دو.صحابہ کو اشارہ کی دیر تھی زینب کا مال
فور واپس کر دیا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد فدیہ کے قائم مقام ابوالعاص کے ساتھ یہ شرط مقرر
کی کہ وہ مکہ میں جا کر زینب کو مدینہ بھیجوا دیں اور اس طرح ایک مومن روح دار کفر سے نجات پاگئی.کچھ
عرصہ بعد ابوالعاص بھی مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر آئے اور اس طرح خاوند بیوی پھر ا کٹھے ہو گئے.حضرت زینب کی ہجرت کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ جب وہ مدینہ کے لئے مکہ سے نکلیں تو مکہ کے چند
قریش نے ان کو بزور واپس لے جانا چاہا.جب انہوں نے انکار کیا تو ایک بد بخت ھبار بن اسود نامی نے
نہایت وحشیانہ طریق پران پر نیزے سے حملہ کیا جس کے ڈر اور صدمہ کے نتیجہ میں انہیں اسقاط ہو گیا ہے
بلکہ اس موقع پر ان کو کچھ ایسا صدمہ پہنچ گیا کہ اس کے بعد ان کی صحت کبھی بھی پورے طور پر بحال نہیں
ہوئی اور بالآخر انہوں نے اسی کمزوری اور ضعف کی حالت میں بے وقت انتقال کیا.سے
قیدیوں میں جو غریب لوگ تھے اور فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارشاد کے ماتحت یونہی بطور احسان رہا کر دیئے گئے ہے مگر جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی رہائی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ مشروط فرمائی کہ دس دس بچوں کو نوشت و خواند سکھا دیں
تو رہا کئے جاویں.چنانچہ زید بن ثابت نے جو بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب خاص کے
بخاری
ابوداؤد
۲: زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۷۹، ۲۸۰ حالات عباس بن عبد المطلب
ابن ہشام
Page 434
۴۱۹
فرائض سرانجام دیتے رہے ہیں.اسی طرح لکھنا پڑھنا سیکھا تھا.قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا جو رؤساء قریش میں سے تھا اور نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھا اور
عموماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیکچر دیتا رہتا تھا.جب وہ بدر میں قید ہوا تو حضرت عمرؓ نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سہیل بن عمرو کے اگلے دانت نکلوا دیے جاویں
تا کہ وہ آپ کے خلاف زہر نہ پھیلا سکے.مگر آپ نے اس تجویز کو بہت نا پسند کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ عمر
تمہیں کیا معلوم ہے کہ خدا آئندہ اسے ایسے مقام پر کھڑا کرے جو قابل تعریف ہو.چنانچہ فتح مکہ کے
موقع پر سہیل مسلمان ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس نے متزلزل لوگوں کو بچانے کے
لئے اسلام کی تائید میں نہایت پر اثر خطبے دیئے جس سے بہت سے ڈگمگاتے ہوئے لوگ بچ گئے اور اسی
سہیل کے متعلق روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں وہ اور ابوسفیان اور بعض
دوسرے رؤساء مکہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر کو ملنے کے لئے گئے.اتفاق سے اسی
وقت بلال اور عمارا اور صہیب وغیرہ بھی حضرت عمرؓ سے ملنے کے لئے آگئے.یہ وہ لوگ تھے جو غلام رہ چکے
تھے اور بہت غریب تھے مگر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا تھا.حضرت عمرؓ
کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے بلال وغیرہ کو پہلے ملاقات کے لئے بلایا.ابوسفیان نے جس کے اندر
غالباً ابھی تک کسی قدر جاہلیت کی رگ باقی تھی یہ نظارہ دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی.چنانچہ
کہنے لگا یہ ذلت بھی ہمیں دیکھنی تھی کہ ہم انتظار کریں اور ان غلاموں کو شرف ملاقات بخشا جاوے.“
سہیل نے فوراً سامنے سے جواب دیا کہ پھر یہ کس کا قصور ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو خدا کی
طرف بلایا لیکن انہوں نے فورامان لیا اور ہم نے دیر کی.پھر ان کو ہم پر فضیلت حاصل ہو یا نہ ہو؟
قیدیوں میں ایک شخص ولید بن ولید تھا جو مکہ کے رئیس اعظم ولید بن مغیرہ کالڑکا اور خالد بن ولید کا بھائی
تھا.صحابہ نے اس سے چار ہزار درہم فدیہ مانگا جو اس کے بھائیوں نے ادا کر دیا اور ولید رہا ہو کر مکہ پہنچ
گیا.مکہ میں پہنچ کر ولید نے اسلام کا اظہار کر دیا.اس کے بھائی اس پر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ تو نے
مسلمان ہی ہونا تھا تو فدیہ کیوں ادا کیا.ولید نے جواب دیا کہ میں نے اس لئے فدیہ ادا کرنے کے بعد
اسلام کا اظہار کیا ہے کہ تالوگ یہ خیال نہ کریں کہ میں فدیہ سے بچنے کے لئے مسلمان ہوا ہوں.اس کے
بعد مکہ والوں نے ولید کو اپنے پاس قید کر لیا اور سخت تکالیف پہنچا ئیں مگر وہ ثابت قدم رہا اور آخر کچھ عرصہ
اصابه واسدالغابہ حالات سہیل بن عمر و
زرقانی جلد ۲ صفحه ۲۱۵
Page 435
۴۲۰
کے بعد موقع پا کر مدینہ بھاگ آیا.مکہ میں جب لشکر قریش کی شکست اور رؤساء قریش کی ہلاکت کی خبر پہنچی تو ایک کہرام مچ گیا اس
حالت کو دیکھ کر ابوسفیان اور بعض دوسرے ذی اثر قریش نے اعلان کروایا کہ کوئی شخص اس وقت تک
مقتولین بدر پر نوحہ نہ کرے جب تک کہ ہم لوگ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ نہ لے لیں اور اس طرح عامتہ الناس
کے جوش نوحہ کو انتقام کی تیاری میں لگا دیا گیا مگر بدر کا صدمہ ایسا نہ تھا کہ عرب کی فطرت اسے آسانی سے
دبا سکتی.چند دن کے صبر و خاموشی کے بعد پھر گھر گھر سے صدائے ماتم بلند ہونی شروع ہوئی اور بدر کے
مقتول مکہ کی گلی کوچوں میں بر ملا طور پر پیٹے جانے لگے.عرب کی سی آتشی فطرت اور پھر بدر کی سی تباہی اس
کے نتیجہ میں جو ماتم بھی ہوسکتا تھا وہ ہوا اور برابر ایک ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا.شروع شروع میں جبکہ
قریش اظہار ماتم سے رکے ہوئے تھے اور پھر جوش ماتم کو دبا نہ سکنے کی وجہ سے پھوٹ پڑے اس وقت کی
ایک مثال روایات میں خاص طور پر مذکور ہوئی ہے اور ناظرین کی بصیرت کے لئے ہم اسے یہاں درج
کرتے ہیں.اسود بن عبد یغوث مکہ کا ایک رئیس تھا.اس کے دولڑ کے اور ایک پوتا جنگ بدر میں مارے
گئے تھے مگر رؤساء قریش کے فیصلہ کی وجہ سے وہ خاموش تھا اور فرط غم سے اندر ہی اندر گھلا جاتا تھا.ایک
رات اس نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے باہر گلی میں سے رونے چلانے کی آواز سنی.اس آواز نے اسے
بے چین کر دیا اور اس نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا دیکھ تو یہ آواز کیسی ہے.شاید رؤساء قریش نے ماتم کرنے
کی اجازت دے دی ہے.اگر یہ درست ہے تو میرے سینے میں ایک آگ لگ رہی ہے میں بھی جی کھول کر
رولوں کہ دل کا کچھ بخار تو نکل جاوے.نوکر گیا اور خبر لایا کہ ایک عورت کا اونٹ کھویا گیا ہے اور وہ اس پر
نوحہ کر رہی ہے.شاعری عرب کی فطرت میں تھی اسود کے منہ سے بے اختیار یہ شعر نکلے اور دبے ہوئے
جذبات پھوٹ کر باہر آ گئے.اَتَبُكِى أَنْ يُضِلَّ لَهَا بَعِيرُ وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُودُ
فَلَا تَبْكِي عَلَى بَكْرٍ وَلَكِن عَلَى بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ
وَبَعِي إِنْ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيلٍ وَبَكَّي حَارِثًا أَسَدِ الْأُسُودِ
یعنی ” کیا وہ عورت اس بات پر رورہی ہے کہ اس کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اور اس نقصان کا غم اسے
رات کو سونے نہیں دیتا.اے عورت! تو اس اونٹ پر کیا روتی ہے.روبدر پر جہاں کہ ہماری قسمت نے
لے اسد الغابه واصابه حالات ولید بن ولید
Page 436
۴۲۱
یاوری نہ کی.ہاں! اگر تو نے رونا ہے تو رو میرے عقیل پر اور رومیرے حارث پر جو شیروں کا شیر تھا.“
غرض اس طرح ماتم کے رکے رہنے کا اعلان دھرے کا دھرا رہ گیا اور ایک ایک کر کے سارے قریش
ماتم کی رو میں بہ گئے.صرف ایک گھر تھا جو خاموش تھا اور وہ ابوسفیان کا گھر تھا.ابوسفیان کی بیوی ہند
قریش کے رئیس اعظم عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی تھی اور یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ بدر کے میدان میں عتبہ اور اس کا
لڑکا ولید اور اس کا بھائی شیبہ سب خاک میں مل چکے تھے ، مگر مردانہ صفت ہند نے ایک لفظ بھی نوحہ کا اپنے
منہ سے نکلنے نہیں دیا.لوگ آ آ کر اس سے پوچھتے تھے کہ اے ہند! تو کیوں خاموش ہے.ہند جواب دیتی
تھی کہ "اگر آنسو میرے غم کی آگ کو بجھا سکتے تو میں بھی روتی لیکن میں جانتی ہوں کہ آنسو میری آگ کو
نہیں بجھا سکتے.اب یہ آگ اس وقت بجھے گی کہ تم لوگ پھر محمد کے خلاف میدان میں نکلو اور بدر کا بدلہ لو."
جنگ بدر کا اثر کفار اور مسلمانوں ہر دو کے لئے نہایت گہرا اور دیر پا ہوا اور اسی لئے تاریخ اسلام میں
اس جنگ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے حتی کہ قرآن شریف میں اس جنگ کا نام یوم الفرقان رکھا گیا
ہے.یعنی وہ دن جبکہ اسلام اور کفر میں ایک کھلا کھلا فیصلہ ہو گیا.بے شک جنگ بدر کے بعد بھی قریش اور
مسلمانوں کی باہم لڑائیاں ہوئیں اور خوب سخت سخت لڑائیاں ہوئیں اور مسلمانوں پر بعض نازک نازک
موقعے بھی آئے لیکن جنگ بدر میں کفار مکہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی جسے بعد کا کوئی جراحی عمل مستقل
طور پر درست نہیں کر سکا.تعدا د مقتولین کے لحاظ سے بے شک یہ کوئی بڑی شکست نہیں تھی.قریش جیسی قوم
میں ستر بہتر سپاہیوں کا مارا جانا ہر گز قومی تباہی نہیں کہلا سکتا.جنگ احد میں یہی تعداد مسلمان مقتولین کی تھی
لیکن یہ نقصان مسلمانوں کے فاتحانہ رستہ میں ایک عارضی روک بھی ثابت نہیں ہوا.پھر وہ کیا بات تھی کہ
جنگ بدر یوم الفرقان کہلائی؟ اس سوال کے جواب میں بہترین الفاظ وہ ہیں جو قرآن شریف نے بیان
فرمائے اور وہ یہ ہیں يَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ.واقعی اس دن کفار کی جڑ کٹ گئی.یعنی جنگ بدر کی ضرب
کفار کی جڑ پر لگی اور وہ دوٹکڑے ہوگئی.اگر یہی ضرب بجائے جڑ کے شاخوں پر لگتی تو خواہ اس سے کتنا زیادہ
نقصان کرتی وہ نقصان اس نقصان کے مقابلہ میں بیچ ہوتا لیکن جڑ کی ضرب نے ہرے بھرے درخت کو
دیکھتے دیکھتے ایندھن کا ڈھیر کر دیا اور صرف وہی شاخیں بچیں جو خشک ہونے سے پہلے دوسرے درخت
سے پیوند ہوگئیں.پس بدر کے میدان میں قریش کے نقصان کا پیمانہ یہ نہیں تھا کہ کتنے آدمی مرے بلکہ یہ
تھا کہ کون کون مرے اور جب ہم اس نقطہ نگاہ سے قریش کے مقتولین پر نظر ڈالتے ہیں تو اس بات میں ذرا
: مغازی الرسول واقدی
ابن ہشام
Page 437
۴۲۲
بھی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ بدر میں فی الواقع قریش کی جڑ کٹ گئی.عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف
اور ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث وغیرہ قریش کی قومی زندگی کی روح رواں تھے اور یہ
روح بدر کی وادی میں قریش سے ہمیشہ کے لئے پرواز کر گئی اور وہ ایک قالب بے جان کی طرح رہ گئے.یہ وہ تباہی تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر یوم فرقان کے نام سے موسوم ہوئی اور خود قریش بھی اس نقصان
کے اندازہ کو خوب سمجھتے تھے.چنانچہ قریش کا ایک معزز شاعر بدر کے مقتولین کا نوحہ کرتا ہوا کہتا ہے اور
کیا خوب کہتا ہے.الا قَدْ سَادَ بَعْدَهُمُ أُنَاسٌ وَلَوْلَا يَوْمُ بَدْرٍ لَمْ يَسُودُوا
ان رؤساء قریش کے بعد کہ جو بدر کے دن مارے گئے ایسے لوگ قومی ریاست کے مسند پر بیٹھے
ہیں کہ اگر بدر کا دن نہ ہوتا تو یہ لوگ ہرگز رئیس نہ بن سکتے.اللہ اللہ کیا تباہی تھی جو اس قوم پر آئی ! بدر کی
شکست کیا تھی کہ گویا قوم رانڈ ہوگئی.بے شک رؤساء زادے اب بھی قریش میں کافی موجود تھے اور وہ
لوگ بھی تھے جو ریاست کی صف دوم میں شمار کئے جاسکتے تھے مگر وہ چوٹی کے سردار جو اسلام کے خلاف
معاندانہ کاروائیوں کی روح رواں تھے اور جن کے پیچھے ان کی قوم با وجود عرب کی فطری آزادی کے اس
معاملہ میں گویا بھیڑوں کی طرح چلتی تھی ، سب کے سب خاک میں مل گئے تھے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس
بارہ میں کوئی خاص تقدیر کام کر رہی تھی کیونکہ ابو لہب جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا مگر جو مخالفین
اسلام کی صف اول میں تھا وہ بھی ہلاکت سے نہیں بچا کیونکہ بدر کے چند دن بعد ہی وہ مکہ میں ایک مکروہ
بیماری میں مبتلا ہوا اور نہایت ذلت کی موت مر کر اپنے ان ساتھیوں سے جاملا جو بدر میں مارے گئے تھے.اب لے دے کے صرف ایک ابوسفیان رہ گیا تھا جسے شاید اس کی قسمت نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان
ہونے کے لئے بچا لیا تھا اور بدر کے بعد اسی کے سر پر قریش کی سرداری کا تاج رکھا گیا تھا.بدر کے
نتائج پر بحث کرتے ہوئے سرولیم میور لکھتے ہیں:
وو
بدر کے حالات میں ایسی باتوں کا بہت کچھ عنصر نظر آتا ہے جس کی وجہ سے محمد صاحب
اس فتح کو جائز طور پر خدائی تقدیر کا کرشمہ شمار کر سکتے تھے.نہ صرف یہ کہ یہ فتح بہت نمایاں
اور فیصلہ کن تھی بلکہ اس جنگ میں غیر معمولی طور پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے اکثر با اثر دشمن
خاک میں مل گئے تھے.ان رؤساء مکہ کے علاوہ جو جنگ میں قتل کئے گئے یا قید کر لئے گئے تھے
ابن ہشام
: ابن ہشام و طبری
Page 438
۴۲۳
ابولہب جو جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا وہ بھی قریش کی بھگوڑی فوج کے مکہ پہنچنے کے چند دن بعد
ہی مکہ میں مر گیا.گویا کہ وہ خدائی حکم جس کی مار رؤساء مکہ پر پڑی ایک اٹل نقد میتھی.دوسری طرف جنگ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں کی پوزیشن نمایاں طور پر مضبوط ہوگئی تھی کیونکہ اوّل
تو اس عظیم الشان اور غیر متوقع فتح کی وجہ سے قبائل عرب پر مسلمانوں کا ایک قسم کا رعب بیٹھ گیا
تھا.دوسرے خود مسلمانوں کی ہمتیں بھی لازماً بلند ہوگئی تھیں اور ایک جائز رنگ خود اعتمادی کا پیدا ہو گیا
تھا.اس فتح کا یہ نتیجہ بھی ہوا کہ منافقین مدینہ مرعوب ہو کر دب گئے اور چونکہ یہ فتح بالکل غیر متوقع حالات
میں حاصل ہوئی تھی اور فریقین کے لئے اپنے نتائج اور اثرات کے لحاظ سے ایک عظیم الشان قومی یادگار تھی
اس لئے مسلمانوں میں جنگ بدر ایک خاص نظر سے دیکھی جانے لگی.چنانچہ جن صحابہ نے اس جنگ میں
حصہ لیا تھاوہ دوسروں سے ممتاز سمجھے جاتے تھے.حتی کہ ایک دفعہ ایک بدری صحابی سے کوئی سخت غلطی سرزد
ہوگئی اور حضرت عمرؓ نے اسے ایک قومی غدار سمجھ کر (حالانکہ در اصل وہ ایک مخلص صحابی تھا مگر اس سے یہ غلطی
ہوگئی تھی ) اسے سزا دینی چاہی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ ” عمر ا تم جانتے نہیں
ہو کہ یہ شخص بدری ہے اور بدریوں کی اس قسم کی غلطیاں اللہ کے نزدیک معاف ہیں.حضرت عمرؓ کے
زمانہ میں بھی جب صحابہ کے وظیفے مقرر ہوئے تو بدری صحابیوں کا وظیفہ ممتاز طور پر خاص مقرر کیا گیا.خود
بدری صحابہؓ بھی جنگ بدر کی شرکت پر خاص فخر کرتے تھے.چنانچہ میور صاحب لکھتے ہیں:
بدری صحابی اسلامی سوسائٹی کے اعلیٰ ترین رکن سمجھے جاتے تھے.سعد بن ابی وقاص
جب اتنی سال کی عمر میں فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ چوغہ لا کر دو جو میں نے بدر
کے دن پہنا تھا اور جسے میں نے آج کے دن کے لئے سنبھال کر رکھا ہوا ہے.یہ وہی سعد تھے جو
بدر کے زمانہ میں بالکل نو جوان تھے اور جن کے ہاتھ پر بعد میں ایران فتح ہوا اور جو کوفہ کے بانی
اور عراق کے گورنر بنے مگر ان کی نظر میں یہ تمام عزتیں اور فخر جنگ بدر میں شرکت کے عزت ونفخر
کے مقابلے میں بالکل پیچ تھیں اور جنگ بدر والے دن کے لباس کو وہ اپنے واسطے سب خلعتوں
،،
سے بڑھ کر خلعت سمجھتے تھے اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ اسی لباس میں لپیٹ کر ان کو قبر
،،
میں اتارا جاوے.“
لائف آف محمد صفحه ۲۲۹،۲۲۸
لائف آف محمد مصنفہ ولیم میور صفحه ۲۲۶، ۲۲۷
بخاری حالات بدر
Page 439
۴۲۴
ط
خدا نے بھی قرآن شریف میں جنگ بدر کے تذکرہ کو خاص اہمیت دی ہے اور سورۃ انفال گویا
ساری کی ساری اسی کے بیان میں ہے اور بدر کے متعلق جو پیشگوئی مکہ میں ہوئی تھی وہ بھی نمایاں طور پر
قرآن شریف میں بیان ہوئی ہے.چنانچہ سورۃ قمر میں اس کا ان الفاظ میں ذکر ہے.أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ
جَمِيع مُنتَصِرُه سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَه بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ
ادهى وَآمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي ضَلٍ وَسُعْرِهُ يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ
ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ! یعنی " کیا یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم انتقام لینے کے لئے جمع ہوئے ہیں؟ یہ لشکر ضرور
پسپا ہوگا اور پیٹھ دکھائے گا بلکہ یہ گھڑی ان کے عذاب کی گھڑی ہوگی.اور یہ وقت ان پر سخت کڑا اور کڑوا
وقت ہوگا.مجرم لوگ گمراہی اور جلانے والے عذاب میں مبتلا ہوں گے.اس وقت یہ لوگ آگ یعنی جنگ
میں اپنے منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ لواب اس آگ کا عذاب چکھو.کیا یہ
پیشگوئی لفظ بلفظ پوری نہیں ہوئی ؟ پھر بصحف گزشتہ میں بھی بدر کا تذکرہ مخصوص طور پر موجود ہے.چنانچہ کتاب یسعیاہ میں عرب کے متعلق الہامی کلام“ کے عنوان کے نیچے یہ پیشگوئی درج ہے:
عرب کے صحرا میں تم رات کاٹو گے.اے دوانیوں کے قافلو! پانی لے کر پیا سے
کا استقبال کرنے آؤ.اے تیما کی سرزمین کے باشندو! روٹی لے کر بھاگنے والے کے ملنے
کو نکلو.کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے نگی تلوار سے اور کھچی ہوئی کمان اور جنگ کی شدت
سے بھاگے ہیں.کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا.ہنوز ایک برس ہاں مزدور کے سے
ٹھیک ایک برس قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیراندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی
بنی قیدار کے بہادر لوگ گھٹ جائیں گے کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں
فرمایا “
الغرض یہ جنگ تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم اور عظیم الشان واقعہ ہے اور اس کے اثرات کفار اور
مسلمانوں ہر دو کے واسطے نہایت گہرے اور دیر پا ثابت ہوئے اور جہاں کفار مکہ کی جڑ کٹ گئی وہاں
ظاہری اسباب کے لحاظ سے مسلمانوں کی جڑ زمین میں قائم ہوگئی لیکن اگر ایک لحاظ سے جنگ بدر کے یہ
: سورة القمر : ۴۵ تا ۴۹
: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا کیا خوب نقشہ ہے
یسعیاہ باب ۲۱ آیات ۱۳ تا ۱۷
مزدور کادن اصل دن سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے.مراد یہ ہے کہ ہم اس معیار کو مزدور کے دن کے حساب سے ایک سال کہہ
رہے ہیں ورنہ اصل میعاد اس سے کچھ زیادہ ہوگی.چنانچہ بدر کی جنگ ہجرت کے ایک سال
اور چند ماہ بعد واقع ہوئی.
Page 440
۴۲۵
خوش کن ثمرات مسلمانوں کے لئے پیدا ہوئے تو دوسرے لحاظ سے وقتی طور پر مسلمانوں کے خطرات بھی بدر
کے بعد زیادہ ہو گئے.کیونکہ لاز مابدر کی تباہی کی وجہ سے کفار مکہ کے سینے جذبہ انتقام سے بھر گئے اور چونکہ
اب قریش کے قومی کاموں کاحل و عقد زیادہ تر نوجوانوں کے ہاتھ میں تھا جو طبعا زیادہ جو شیلے اور عواقب کی
طرف سے بے پروا ہوتے ہیں اس لئے بدر کے بعد مدینہ پر کفار کے حملہ کا خطرہ زیادہ مہیب صورت اختیار
کر گیا.دوسری طرف دوسرے قبائل عرب جہاں جنگ بدر سے مرعوب ہوئے وہاں مسلمانوں کی طرف
سے ان کا فکر آگے سے بھی زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے یہ خیال کرنا شروع کیا کہ اگر اسلام کو مٹانے
اور مسلمانوں
کو تباہ و برباد کرنے کی کوئی صورت جلدی نہ ہوئی تو یہ قوم ملک میں اس قدر مضبوط ہو جائے گی
کہ پھر اس کا مٹانا ناممکن ہوگا ، اس لئے جنگ بدر کے نتیجہ میں ان کی معاندانہ کوششیں زیادہ عملی اور خطرناک
صورت اختیار کرگئیں اور یہودان مدینہ بھی چونک کر ہوشیار ہو گئے.ایک اور خطرناک نتیجہ بدر کا یہ نکلا کہ
کفار مکہ جواب تک صرف ظاہری زور اور گھمنڈ پر لڑ رہے تھے اب ایک کھلے میدان میں مسلمانوں سے زک
اٹھا کر مخفی اور درپردہ سازشوں کی طرف بھی مائل ہونے لگ گئے.چنانچہ ذیل کا تاریخی واقعہ جو جنگ بدر کے
صرف چند دن بعد وقوع میں آیا اس خطرہ کی ایک بین مثال ہے لکھا ہے کہ بدر کے چند دن بعد عمیر بن
وہب اور صفوان بن امیہ بن خلف جو ذی اثر قریش میں سے تھے صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم
کر رہے تھے کہ اچانک صفوان نے عمیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تو جینے کا کوئی مزا نہیں رہا.عمیر نے
اشارہ تاڑا اور جواب دیا کہ ”میں تو اپنی جان خطرہ میں ڈالنے کے لئے تیار ہوں لیکن بچوں اور قرض کا
خیال مجھے مانع ہو جاتا ہے.ورنہ معمولی بات ہے مدینہ جا کر چپکے سے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کا خاتمہ
کر آؤں اور میرے لئے وہاں جانے کا یہ بہانہ بھی موجود ہے کہ میرا لڑکا ان کے پاس قید ہے.“ صفوان
نے کہا.” تمہارے قرض اور بچوں کا میں ذمہ دار ہوتا ہوں تم ضرور جاؤ اور جس طرح بھی ہو یہ کام
کرگزرو.غرض تجویز پختہ ہوگئی اور صفوان سے رخصت ہو کر عمیر اپنے گھر آیا اور ایک تلوار زہر میں بجھا کر
مکہ سے نکل کھڑا ہوا جب وہ مدینہ پہنچا تو حضرت عمر نے جو ان باتوں میں بہت ہوشیار تھے اسے دیکھ
کر خوفزدہ ہوئے اور فوراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ عمیر آیا ہے اور مجھے اس کے متعلق
اطمینان نہیں ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ.حضرت عمر سے لینے
کے لئے گئے.مگر جاتے ہوئے بعض صحابہ سے کہہ گئے کہ میں عمیر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے
کے لئے لاتا ہوں مگر مجھے اس کی حالت مشتبہ معلوم ہوتی ہے تم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
Page 441
۴۲۶
جا کر بیٹھ جاؤ اور چوکس رہو.اس کے بعد حضرت عمرؓ عمیر کو ساتھ لئے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اسے نرمی کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر پوچھا ” کیوں عمیر کیسے آنا ہوا ؟“
عمیر نے کہا "میرالڑ کا آپ کے ہاتھ میں قید ہے اسے چھڑانے آیا ہوں.آپ نے فرمایا ” تو پھر یہ تلوار
کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ اس نے کہا ”آپ تلوار کا کیا کہتے ہیں.بدر میں تلواروں نے کیا کام دیا.“
آپ نے فرمایا ”نہیں ٹھیک ٹھیک بات بتاؤ کہ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا بات وہی ہے جو میں کہہ چکا
ہوں
کہ بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں.آپ نے فرمایا اچھا تو گویا تم نے صفوان کے ساتھ مل کر صحن کعبہ میں کوئی
سازش نہیں کی.عمیر سناٹے میں آ گیا.مگر سنبھل کر بولا ”نہیں میں نے کوئی سازش نہیں کی.آپ نے
فرمایا ” کیا تم نے میرے قتل کا منصوبہ نہیں کیا ؟ مگر یاد رکھو خدا تمہیں مجھ تک پہنچنے کی توفیق نہیں دے
گا.عمیر ایک گہرے فکر میں پڑ گیا اور پھر بولا ” آپ سچ کہتے ہیں ہم نے واقعی یہ سازش کی تھی.مگر معلوم
ہوتا ہے خدا آپ کے ساتھ ہے جس نے آپ کو ہمارے ارادوں سے اطلاع دے دی ورنہ جس وقت
میری اور صفوان کی بات ہوئی تھی اس وقت وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا اور شاید خدا نے یہ تجویز
میرے ایمان لانے ہی کے لئے کروائی ہے اور میں سچے دل سے آپ پر ایمان لاتا ہوں.“ آپ عمیر کے
اسلام سے خوش ہوئے اور صحابہ سے فرمایا.اب یہ تمہارا بھائی ہے اسے اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرو اور اس
کے قیدی کو چھوڑ دو.الغرض عمیر بن وہب مسلمان ہو گئے اور بہت جلد انہوں نے ایمان واخلاص میں
نمایاں ترقی کر لی اور بالآخر نور صداقت کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
باصرار عرض کیا کہ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں کے لوگوں کو جا کر تبلیغ کروں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور عمیر نے مکہ پہنچ کر اپنے جوش تبلیغ سے کئی لوگوں
کو خفیہ خفیہ
مسلمان بنالیا.صفوان جو دن رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنے کا منتظر تھا اور قریش سے کہا
کرتا تھا کہ اب تم ایک خوشخبری سننے کے لئے تیار رہو.اس نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بے خود سارہ گیا.اگر اس جگہ کسی کو یہ سوال پیدا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس طرح علم ہو گیا کہ عمیر اس نیت
سے آیا ہے تو اس کا سیدھا اور سادہ جواب یہ ہے کہ جس خدا نے آپ کو دنیا کی اصلاح کے لئے نبی بنا کر
بھیجا تھا اور جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے اسی نے آپ کو اطلاع دے دی.دراصل آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ آپ کوئی معمولی انسان نہ تھے بلکہ
ابن ہشام و طبری
Page 442
۴۲۷
آپ کو خدا کی طرف سے نبی اور رسول بلکہ خاتم النبیین ہونے کا دعوی تھا.لہذا ضروری ہے کہ آپ کی
سیرت وسواخ کا منہاج نبوت کی روشنی میں مطالعہ کیا جاوے.پس جس طرح ضرورت زمانہ کے ماتحت
دوسرے انبیاء ومرسلین کو اللہ غیب کی باتوں پر آگاہ کرتا رہا ہے اور ان کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً خوارق ومعجزات
ظاہر ہوتے رہے ہیں اسی طرح ضروری تھا کہ آپ کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے علم وقدرت کی مخفی طاقتوں
کا اظہار کرے اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر ہم دنیا کی دوسری باتوں
کو معتبر لوگوں کی شہادت کی وجہ سے مانتے ہیں
تو آیات و معجزات کو معتبر شہادت کے ہوتے ہوئے نہ مانیں.البتہ جس طرح دوسری باتوں میں تحقیق کے بعد
ایک بات کو مانا جاتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ آیات و معجزات کے متعلق پوری پوری
تحقیق سے کام لیا جاوے اور صرف اسی بات کو مانا جاوے جو معتبر شہادت سے پایہ ثبوت کو پہنچی ہوئی ہو
تا کہ غلط اور موضوع قصے صحیح تاریخ کا حصہ نہ قرار پا جائیں ، مگر یہ ایک نازک اور اہم مسئلہ ہے جس کے
متعلق مفصل بحث انشاء اللہ کسی اور موقع پر آئے گی.بدر کا اثر مشرکین مدینہ پر
ابھی تک مدینہ میں قبائل اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ شرک پر قائم
تھے.بدر کی فتح نے ان لوگوں میں ایک حرکت پیدا کر دی اور ان میں سے
بہت سے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان اور خارق عادت فتح کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت
کے قائل ہو گئے.اور اس کے بعد مدینہ سے بت پرست عنصر بڑی سرعت کے ساتھ کم ہونا شروع ہو گیا مگر
بعض ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں اسلام کی اس فتح نے بغض و حسد کی چنگاری روشن کر دی اور انہوں نے
بر ملا مخالفت کو خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا لیکن اندر ہی اندر اس کے استیصال کے
در پے ہو کر منافقین کے گروہ میں شامل ہو گئے.ان مؤخر الذکر لوگوں میں زیادہ ممتاز عبداللہ بن ابی ابن سلول
تھا جو قبیلہ خزرج کا ایک نہایت نامور رئیس تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے
کے نتیجہ میں اپنی سرداری کے چھینے جانے کا صدمہ اٹھا چکا تھا.یہ شخص بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہو گیا لیکن
اس کا دل اسلام کے خلاف بغض و عداوت سے لبریز تھا اور اہل نفاق کا سردار بن کر اس نے مخفی مخفی اسلام اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دوانی کا سلسلہ شروع کر دیا.چنانچہ بعد کے واقعات سے پتہ لگے گا
کہ کس طرح یہ شخص بعض اوقات اسلام کے لئے نہایت نازک حالت پیدا کر دینے کا باعث بنا.رومی سلطنت کی فتح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کتاب کے حصہ اول میں
بیان کیا گیا تھا کہ ان ایام
Page 443
۴۲۸
میں روم اور فارس کی مملکتیں بر سر پریکار تھیں اور مکہ والوں کی ہمدردی طبعا اہل فارس کے ساتھ تھی جو انہی کی
طرح مشرک تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تشریف رکھتے تھے کہ آپ نے خدا سے الہام
پا کر یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ اس جنگ میں گو ابتداء روم کو نیچا دیکھنا پڑے گا لیکن بالآخر ا سے فارس پر فتح
حاصل ہوگی اور تین سال سے لے کر نو سال کے عرصہ تک روم غالب آ جائے گا.یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی
تھی جبکہ فارس کی افواج روم کو دباتی چلی جاتی تھیں اور بہت سے رومی علاقے فارس نے چھین لئے تھے
اور بظاہر حالات روم کے لئے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی.اس حالت کو دیکھ کر کفار مکہ بہت خوش تھے اور
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تو وہ کہتے تھے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اب روم کو غلبہ
حاصل ہو.چنانچہ ان کی تحریک پر حضرت ابو بکر نے ان سے ایک شرط بھی باندھ لی.مگر حضرت ابو بکر سے
ی غلطی ہوئی کہ انہوں نے کفار مکہ کے کہنے میں آکر قرآن شریف کی بیان کردہ میعاد کو جو تین سال سے لے
کر نو سال کے عرصہ پر مشتمل تھی صرف چھ سال میں محصور کر دیا اور اس طرح قریش کو ایک جھوٹی خوشی
کا موقع مل گیا مگر بعد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی کہ خدائی میعاد کوٹنگ
کرنے کا کسی کوحق نہیں ہے پوری میعاد نو سال ہے اور اس وقت تک پیشگوئی کے پورا ہونے کا انتظار کرنا
چاہئے.چنانچہ ابھی نو سال نہیں گزرے تھے کہ جنگ نے یکلخت پلٹا کھایا اور روم نے فارس کو شکست پر
شکست دے کر اپنا سارا علاقہ واپس چھین لیا اور جنگ کا اختتام روم کی فتح پر ہوا.یہ ایام وہی تھے جبکہ صحابہ
نے قریش مکہ کو بدر کے میدان میں شکست دی تھی.گویا اس موقع پر مسلمانوں کے لئے دو خوشیاں جمع
ہوگئیں اور قریش مکہ کے لئے دو ماتم کے بعض روایات میں یہ مروی ہوا ہے کہ یہ فتح روم کو صلح حدیبیہ کے
زمانہ میں حاصل ہوئی تھی مگر یہ دونوں روایتیں متضاد نہیں ہیں کیونکہ دراصل روم کی فتح کا زمانہ جنگ بدر
سے لے کر صلح حدیبیہ کے زمانہ تک پھیلا ہوا تھا.اس وقت تک اسلام میں شرط باندھنا ممنوع نہیں تھا.: قرآن شریف سورۃ روم اور ترمذی جلد۲ تفسیر سورۃ روم.لائف آف محمد مصنفہ سرولیم میورصفحہ ۱۱۸.۱۱۹ وانسائیکلوپیڈیا
برٹینیہ کا حالات ہر قل.
Page 444
۴۲۹
غلاموں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
سلوک اور مسئلہ غلامی کے متعلق آپ کی تعلیم
مسئلہ غلامی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کو غلامی کے مسئلہ کے ساتھ ایک بنیادی
تعلق ہے اور بدر وہ پہلی با قاعدہ جنگ ہے جو کفار
اور مسلمانوں کے درمیان وقوع میں آئی.اس لئے جنگ بدر کے تذکرہ میں طبعا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ غلامی کے متعلق کیا تعلیم دی اور کیا طریق اختیار کیا؟ لہذا پیشتر اس کے
کہ ہم آگے چلیں مسئلہ غلامی کے متعلق ایک مختصر سا نوٹ درج کرنا نا مناسب نہ ہوگا.مگر چونکہ یہ مسئلہ
نہایت وسیع اور نہایت نازک ہے اور اس پر پورے تبصرہ کے لئے بہت سے مباحث میں داخل ہونا پڑتا
ہے جس کی اس جگہ گنجائش نہیں اور نہ ایک مؤرخ ہونے کی حیثیت میں ہم اس قسم کی علمی بحثوں میں زیادہ
پڑ سکتے ہیں ، اس لئے ہم اس جگہ صرف اصولی نقطہ نگاہ سے اس مسئلہ پر ایک اجمالی نظر ڈالیں گے اور
اس میں بھی اپنے آپ کو صرف اس حد تک محدود رکھیں گے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریق عمل
کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے.سوسب سے پہلے تو یہ جاننا چاہئے کہ جیسا کہ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں تصریح کی گئی ہے دنیا میں غلامی
کی ابتدا در اصل جنگ سے ہوئی ہے.شروع شروع میں غلام بنائے جانے کا طریق اس طرح پر جاری ہوا
کہ جب دو قبیلوں یا دو قوموں یا دو ملکوں کے درمیان کسی وجہ سے جنگ چھڑتی تھی تو مفتوح فوج کے جنگجو
لوگ بلکہ بسا اوقات مفتوح قوم کے پیشتر یا سارے کے سارے مرد قتل کر دیئے جاتے تھے اور عورتوں اور
بچوں کو (سوائے اس کے کہ انہیں بھی واجب القتل سمجھا جاوے ) قید کر کے غلام بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان
غلاموں سے مختلف قسم کے کام اور محنتیں لی جاتی تھیں.اس کے بعد ایک طرف دنیا میں تمدن اور کاروبار نے
Page 445
۴۳۰
ترقی کی اور مزدور پیشہ لوگوں اور خدمتگاروں کی مانگ زیادہ ہونی شروع ہوئی اور دوسری طرف عورتوں اور
بچوں کو غلام بنا لینے کے عملی تجربہ نے یہ ثابت کیا کہ خدمت اور مزدوری حاصل کرنے کا یہ ایک عمدہ
اور آسان ذریعہ ہے کہ مفتوح قوم کے لوگوں کو غلام بنا کر رکھا جاوے اس لئے آہستہ آہستہ یہ طریق جاری
ہو گیا کہ باستثنا ان لوگوں کے جو کسی وجہ سے واجب القتل سمجھے جاتے تھے مفتوح قوم کے مردوں کو بھی
بجائے قتل کرنے کے غلام بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان سے ملکی اور قومی اور انفرادی کاموں میں جبری محنت لی
جاتی تھی.اس طرح آہستہ آہستہ یہ طریق ایسا وسیع ہو گیا کہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ بعض ممالک میں
غلاموں کی تعداد اصل باشندوں سے بھی زیادہ ہو گئی اور غلامی کا طریق دنیا کے تمدن اور معاشرت کا ایک
ضروری حصہ بن گیا.یہ غلام مالک کی کامل ملکیت سمجھے جاتے تھے اور اسے اختیار حاصل ہوتا تھا کہ انہیں
جس طرح چاہے رکھے.جو کام چاہے ان سے لے.جو سزا چاہے انہیں دے اور جب اور جس طرح
چاہے انہیں کسی اور شخص کے پاس فروخت کر دے.اور بالآخر اس سلسلہ نے ایسی وسعت اختیار کر لی کہ ان غلاموں کی اولاد بھی مالک کی ملک متصور
ہونے لگی.اور اس طرح ایک مستقل اور غیر متناہی سلسلہ غلامی کا جاری ہو گیا اور جب لوگوں نے یہ دیکھا
کہ یہ ایک بڑا فائدہ مند سلسلہ ہے کہ گویا مفت میں ایسے نوکروں اور مزدوروں کی خدمت حاصل ہو جاتی
ہے جن کو کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں دینی پڑتی اور جو ہر حالت میں اور ہر قسم کی خدمت پر مجبور ہوتے تھے بلکہ علاوہ
خدمت کے ان سے اور بھی بعض فائدے اٹھائے جاسکتے ہیں تو جنگی قیدیوں کے طریق کے علاوہ لوگوں
نے اور بھی کئی قسم کے ظالمانہ طریق غلام بنانے کے ایجاد کر لئے.مثلاً بلا وجہ کسی کمز ور قبیلہ یا قافلہ پر حملہ
کر کے ان کے مردوزن کو پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان بدنصیب لوگوں کی نسل میں یہ غلامی کا داغ
ہمیشہ کے لئے چلتا چلا جاتا تھا.الغرض آہستہ آہستہ غلامی کا جائز و ناجائز طریق دنیا میں رائج اور مستحکم
ہو گیا اور جس وقت اسلام کی ابتداء ہوئی اس وقت تمام ممالک میں یہ طریق کم و بیش جاری تھا اور مملکت ہائے
روم اور یونان اور ایران وغیرہ میں لاکھوں غلام دیکھ اور مصیبت کی زندگی کاٹ رہے تھے اور کوئی ان کا
پرسان حال نہیں تھا اور بحیثیت مجموعی ان کی حالت جانوروں سے بڑھ کر نہیں تھی.اس زمانہ میں عرب کے
ملک میں بھی ہزار ہا غلام پائے جاتے تھے اور امراء کی امارت میں غلاموں کی تعداد بھی گویا ایک ضروری
حصہ سمجھی جاتی تھی اور عرب کے لوگ خصوصیت کے ساتھ غلاموں کو سخت حقیر وذلیل خیال کرتے تھے
اور جیسا بھی ظالمانہ سلوک چاہتے تھے ان سے کرتے تھے.چنانچہ کتاب کے حصہ اول میں گزر چکا ہے کہ
Page 446
۴۳۱
مسلمان ہونے والے غلاموں پر رؤساء مکہ نے کیسے کیسے سخت مظالم کئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا سے الہام پا کر رسالت کا دعویٰ کیا تو آپ کی ابتدائی
تعلیمات میں یہ بات بھی داخل تھی کہ غلاموں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک ہونا چاہئے.اور غلاموں
کے آزاد کئے جانے کے متعلق بھی آپ نے اسی ابتدائی زمانہ میں تحریک شروع کر دی تھی بلکہ اس بارہ میں تو
خصوصیت کے ساتھ ایک قرآنی وحی بھی نازل ہوئی کہ غلام کا آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے.اسلامی
تعلیم کی خوبی اور کشش کے ساتھ اس مخصوص تعلیم نے مل کر عرب کے غلاموں پر ایک نہایت گہرا اثر پیدا کیا
اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اپنے لئے ایک نجات دہندہ کی آواز سمجھنے لگ گئے.یہی وجہ تھی کہ
با وجو دان نہایت درجہ بے دردانہ مظالم کے جو رؤساء مکہ مسلمان ہونے والوں پر کرتے تھے ، غلاموں میں
اسلام بڑی سرعت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا.چنانچہ جیسا کہ کتاب کے حصہ اول میں بیان کیا جا چکا ہے
ابتدائی مسلمانوں میں غلاموں کی نسبت غیر معمولی طور پر زیادہ تھی اور تاریخ سے ثابت ہے کہ یہ لوگ ابتدائی
زمانہ میں بھی اسلامی سوسائٹی میں ہرگز ذلیل نہیں سمجھے جاتے تھے.اس کے بعد جوں جوں اسلامی احکام
نازل ہوتے گئے غلاموں کی پوزیشن زیادہ مضبوط اور ان کی حالت زیادہ بہتر ہوتی گئی اور بالآخر اس انتظامی
فرق کے سوا کہ ایک افسر ہوتا تھا اور دوسرا اس کے ماتحت کوئی اور امتیاز باقی نہ رہا.دوسری طرف غلاموں
کی آزادی کی تحریک بھی دن بدن زیادہ مضبوط ہوتی گئی اور مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
پر زور تعلیم اور آپ کے عملی نمونہ کے ماتحت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا.چنانچہ
قرآن شریف اور کتب حدیث و تاریخ اس کی تفاصیل سے بھری پڑی ہیں.مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اس حد تک محدود رہا ہے
جو اوپر بیان کیا گیا ہے اور آپ نے غلامی کے ناجائز اور ظالمانہ طریقوں کو منسوخ کرنے کے لئے کوئی
تدابیر اختیار نہیں کیں؟ اگر یہی ہے تو گو پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایک عظیم الشان محسن قرار
پاتے ہیں کہ آپ نے غلاموں کی حالت کو بہتر بنانے اور ان کی آزادی کی تحریک جاری کرنے اور اس
تحریک کو عملی جامہ پہنانے میں ایک نہایت نمایاں خدمت سر انجام دی مگر یقینا اس سے آپ کا وہ حقیقی کام
پردہ میں رہتا ہے جو آپ کی اس تحریک کی اصل روح رواں تھا کیونکہ جہاں تک ہماری تحقیق ہے اور یہ
تحقیق خوش عقیدگی کا ثمرہ نہیں بلکہ تاریخی واقعات پر مبنی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غلاموں
: سورة البلد : ۱۱ تا ۱۴
Page 447
۴۳۲
کی حالت کو بہتر ہی نہیں بنایا بلکہ آپ نے آئندہ کے لئے غلامی کے ناجائز اور ظالمانہ طریقوں کو منسوخ
بھی کر دیا.گویا مسئلہ غلامی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں اصلاح کا کام دو
حلقوں میں تقسیم شدہ تھا.اول حاضر الوقت غلاموں کی حالت کی اصلاح اور ان کی آزادی کا انتظام.دوم آئندہ کے لئے
اصولی احکامات اور ہم اس جگہ ان دونوں قسم کے کاموں کے متعلق آپ کی تعلیم اور آپ کے طریق عمل کا
نمونه مختصر طور پر ہدیہ ناظرین کرتے ہیں.موجود الوقت غلاموں کی اصلاح کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
طبعی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہم اس بحث کو لیتے ہیں جو حاضر الوقت غلاموں سے تعلق رکھتی
ہے.سو جاننا چاہئے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ بِذِي الْقُرْبى وَالْيَتَى وَالْمَسْكِينِ.....وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا )
”اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کا
سلوک کرو اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اور قیموں اور مسکینوں کے ساتھ.اور اپنے
غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو تکبر اور بڑائی کا
طریق اختیار کرتے ہیں.“
اس آیت میں غلاموں کے ساتھ نیکی اور احسان کا حکم دیا گیا ہے.پھر فرماتا ہے:
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَتُكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنْ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
”اوراے مسلمانو! نہ شادی کرو تم مشرک عورتوں کے ساتھ حتی کہ وہ ایمان لے آئیں
اور جانو کہ ایک مسلمان لونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرک عورت سے خواہ تمہیں مشرک عورت
اچھی ہی نظر آئے.اور اے مسلمانو ! نہ نکاح کرو مسلمان عورتوں کا تم مشرک مردوں کے ساتھ
حتی کہ وہ ایمان لے آئیں اور جانو کہ ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک آدمی سے خواہ
: سورۃ النساء : ۳۷
: سورة البقره : ۲۲۲
b
Page 448
۴۳۳
تمہیں مشرک آدمی اچھا ہی نظر آئے.“
اس آیت میں علاوہ اس کے کہ غلاموں کی پوزیشن کو نمایاں طور پر مضبوط کیا گیا ہے.آزاد مسلمان
مردوں اور عورتوں اور مسلمان لونڈیوں اور غلاموں کے باہمی شادیوں کے لئے دروازہ کھولا گیا ہے تا اس
مساویانہ اور رشتہ دارانہ اختلاط کے نتیجہ میں غلاموں کی حالت جلد تر اصلاح پذیر ہو سکے.چنانچہ منجملہ
اور مصالح کے اس اصل کے ماتحت قرآن شریف میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ چار بیویوں کی انتہائی
اور استثنائی حد کے پورا ہو چکنے کے بعد بھی اگر کسی مسلمان کے لئے کسی غلام عورت کے ساتھ رشتہ کرنے کا
سوال پیدا ہوتو یہ چار کی حد بندی اس کے رستہ میں روک نہیں ہوگی اور وہ ہر حالت میں غلام عورت کے
ساتھ رشتہ کر سکے گا.تا کہ غلاموں کی حالت کی اصلاح کا رستہ کسی صورت میں بھی مسدود نہ ہونے
پائے.پھر فرماتا ہے:
لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ا
اوراے رسول! جو شادیاں تم اب تک کر چکے ہو یہ تمہاری تبلیغی تربیتی اور سیاسی
ضروریات کے لئے کافی ہیں اس لئے ) اب اس کے بعد تمہیں کوئی اور شادی کرنے کی اجازت
نہیں ہے.البتہ اگر کسی غلام عورت کے ساتھ رشتہ کا سوال
پیدا ہو تو تمہیں اس کی اجازت ہے.“
یہ حکم بھی اسی غرض وغایت کا حامل ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے اور اس میں مزید غرض یہ شامل ہے
کہ تا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل سے مسلمانوں کے لئے ایک بہترین نمونہ قائم ہو جاوے.پھر فرماتا ہے:
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ "
یعنی اے مسلمان عورتو! تم اپنی زینت سوائے اپنے خاوندوں اور فلاں فلاں قریبی رشتہ داروں
کے کسی پر ظاہر نہ کیا کرو.یعنی پردے کی ان حدود کو مدنظر رکھو جو تمہارے لئے مقرر کی گئی
ہیں.البتہ تمہیں اپنے غلاموں سے پردہ نہیں کرنا چاہئے.“
اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلاموں کے متعلق اسلامی تعلیم کا اصل منشاء یہ تھا کہ مسلمان انہیں بالکل
اپنے قریبی عزیزوں کی طرح سمجھیں حتی کہ مسلمان عورتیں اپنے غلاموں سے پردہ بھی نہ کریں تا کہ غیریت
کا احساس بالکل جاتا رہے اور رشتہ داروں کا سا اختلاط پیدا ہو جائے.: سورة النساء : ۴
سورۃ احزاب : ۵۳
۳ : سورۃ نور : ۳۲
Page 449
۴۳۴
پھر حدیث میں آتا ہے:
رهم
عَنْ أَبِي ذَرِّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ
تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوُهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمُهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلاَ تُكَلِّفُو
مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاعِيُنُوهُمْ.یعنی ابوذر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ” تمہارے
غلام تمہارے بھائی ہیں.پس جب کسی شخص کے ماتحت کوئی غلام ہو تو اسے چاہئے کہ اسے وہی
کھانا دے جو وہ خود کھاتا ہے اور وہی لباس دے جو وہ خود پہنتا ہے اور تم اپنے غلاموں کو ایسا
کام نہ دیا کرو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو اور اگر کبھی ایسا کام دو تو پھر اس کام میں خودان
کی مدد کیا کرو.“
اور مدد کرنے کے الفاظ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ کام ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ اگر وہ آقا کو خود کرنا
پڑے تو وہ اسے اپنے لئے موجب عار سمجھے بلکہ ایسا ہونا چاہئے کہ جسے آقا خود بھی کر سکتا ہو اور کرنے کو تیار
ہو.یہ حدیث اپنے مطالب میں نہایت واضح ہے اور اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی لائی ہوئی تعلیم میں نہ صرف یہ کہ غلاموں کے ساتھ کامل درجہ کے حسن سلوک اور انتہائی شفقت کا حکم دیا
گیا ہے جس کی نظیر یقینا کسی اور مذہب اور کسی اور قوم میں نہیں ملتی بلکہ یہ کہ در حقیقت اس تعلیم کا اصلی منشا
تھا کہ مسلمان اپنے غلاموں کو بالکل اپنے بھائیوں کی طرح سمجھیں اور ہر امر میں جس طرح خود رہتے ہیں
اسی طرح انہیں رکھیں تا کہ ان کے تمدن و معاشرت میں اسی طرح کی بلندی پیدا ہو جائے جیسی کہ دوسرے
آزا دلوگوں میں ہے اور ان کے دلوں سے پستی کے احساسات بالکل مٹ جائیں اور نہ محض حسن سلوک کی
غرض سے اس قدر انتہائی تعلیم نہیں دی جاسکتی تھی کہ غلاموں کو بعینہ اسی طرح رکھو جس طرح کہ خود رہتے ہو
کیونکہ حفظ مراتب تو ہوا ہی کرتا ہے اور اسلام اسے تسلیم کرتا ہے.پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبَادَةَ الصَّامِتِ قَالَ لَقِيْنَا اَبَا الْيُسْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غُلَامٌ وَعَلَيْهِ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ وَعَلَى غُلَامِهِ بُرُدَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ قَالَ
قُلْتُ لَهُ يَاعَمِّ لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرُدَةَ غُلَامِكَ وَاعْطَيْتَهُ مَعَافِرَيْكَ وَاَخَذْتَ مَعَافِرَيْهِ
بخاری کتاب العتق
Page 450
۴۳۵
وَاعْطَيْتَهُ بُرْدَتَكَ فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ قَالَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ
بَارِكْ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بَصَرَتْ عَيْنَايَ هَاتَانِ وَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ هَاتَانِ وَوَعَاهُ
قَلْبِي هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا
تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُونَ فَكَانَ إِنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ
أَنْ يَّاخُذَ مِنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
یعنی ” عبادہ بن ولید روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
ابوالیسر کو ملے.اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا اور ہم نے دیکھا کہ ایک دھاری دار
چادر اور ایک یمنی چادر ان کے بدن پر تھی اور اسی طرح ایک دھاری دار چادر اور ایک یمنی چادر
ان کے غلام کے بدن پر تھی.میں نے انہیں کہا چچا تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اپنے غلام کی دھاری دار
چادر خود لے لیتے اور اپنی چادر اسے دے دیتے یا اس کی یمنی چادر خود لے لیتے اور اپنی دھاری دار
چادر اسے دے دیتے تا کہ تم دونوں کے بدن پر ایک ایک طرح کا جوڑا تو ہو جاتا.ابوالیسر
نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے دعا کی اور کہا بھتیجے! میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے
اور میرے ان کانوں نے سنا ہے اور میرے اس دل نے اسے اپنے اندر جگہ دی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے غلاموں کو وہی کھانا کھلا ؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہی
لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو.پس میں اس بات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں دنیا کے
اموال میں سے اپنے غلام کو برابر کا حصہ دے دوں بہ نسبت اس کے کہ قیامت کے دن میرے
ثواب میں کوئی کمی آوے.“
یہ حدیث اپنے الفاظ کے زور دار ہونے میں گزشتہ حدیث سے بھی زیادہ واضح ہے اور اس سے یہ بھی
پتہ لگتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر صحابہ عمل بھی کرتے تھے.بلکہ اس
کی تعمیل میں انہیں
اس درجہ انہاک تھا کہ وہ اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے اور ان کے غلاموں کے لباس میں
درجہ کا اختلاف تو الگ رہا ظاہری صورت کا بھی خفیف سا اختلاف پیدا ہو..پھر روایت آتی ہے:
عَنْ أَبِي النَّوَارِ بَيَّاعِ الْكَرَابِيسِ قَالَ أَتَانِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ
: مسلم كتاب الزهد ملخصا
Page 451
۴۳۶
فَاشْتَرى مِنِّى قَمِيصَى كَرَابِيْسَ فَقَالَ لِغُلامِهِ اخْتَرَاَيْهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَأَخَذَ
عَلِيُّ الْآخَرَ فَلَبَسَهُ
یعنی ” ابونوار جو روئی کے کپڑوں کی تجارت کرتے تھے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ
حضرت علی ان کی دوکان پر آئے.اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا علی نے دو
ٹھنڈی قمیصیں خریدیں اور پھر اپنے غلام سے کہنے لگے کہ ان میں سے جو قمیص تم چاہو لے لو.چنانچہ غلام نے ایک قمیص چن لی اور جو دوسری قمیص رہ گئی وہ حضرت
علی نے خود پہن لی.“
اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت خاص خاص صحابہ
بعض اوقات یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ اپنی چیزوں میں سے انتخاب کا حق پہلے غلام کو دیتے تھے اور
پھر جو چیز باقی رہ جاتی تھی وہ خود استعمال کرتے تھے.یہ انتہائی درجہ کا ایثار ہے جو کوئی شخص کسی دوسرے
شخص کے لئے کر سکتا ہے اور یقیناً غلاموں کے متعلق اس درجہ کا ایثار محض حسن سلوک کی غرض سے نہیں
ہوسکتا بلکہ اس میں وہی دور کی غرض بھی مد نظر تھی کہ یہ غلام جلد تر اپنے اخلاق اور معاشرت میں آزا دلوگوں
کے مرتبہ کو پہنچ کر آزاد کر دیئے جانے کے قابل ہو جائیں.پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُلْ اَحَدُكُمُ
عَبْدِي اَمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَلْيَقُلْ سَيِّدِى وَمَوْلاَيَ
یعنی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے
مسلمانو! تم یوں نہ کہا کرو کہ ” میرا غلام میری لونڈی بلکہ یوں کہا کرو کہ میرا آدمی میری عورت“
اور غلام بھی اپنے آقا کو رب یعنی مالک نہ کہا کرے بلکہ سید اور بزرگ کہہ کر پکارا کرے.“
اس حدیث میں آقا اور غلام کی ذہنیتوں کو درست کیا گیا ہے.یعنی جہاں ایک طرف آقا کے دل
ودماغ سے بڑائی اور تکبر کے خیالات کو مٹایا گیا ہے.وہاں دوسری طرف غلام کے دل میں خود داری
اور عزت نفس کے جذبات پیدا کئے گئے ہیں اور عملی اور معاشرتی اصلاح کے ساتھ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے
یہ ذہنی اصلاح مل کر سونے پر سہاگے کا کام دیتی ہے اور اس کے بعد حالات اور خیالات کی کامل تبدیلی
میں کوئی امر مانع نہیں رہتا.اسی طرح اور بھی بہت سی احادیث اور آثار ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
اسدالغا به حالات حضرت علی جلد ۴ صفحه ۲۴
بخاری کتاب العتق
Page 452
۴۳۷
نہ صرف یہ کہ اسلام میں موجود الوقت غلاموں کی اصلاح اور ان کی بہبودی اور آرام و آسائش کے متعلق
انتہائی درجہ کا زور دیا گیا ہے بلکہ یہ کہ اس تعلیم میں اسلام کا اصل منشا یہ تھا کہ غلاموں اور ان کے مالکوں کے
تمدن و معاشرت اور عزت و آبرو کو ایک مساویانہ درجہ پر لا کر غلاموں کو جلد تر اس قابل بنا دیا جاوے کہ
وہ آزاد ہو کر ملک کے مفید اور کارآمد شہری بن سکیں.یہ بھی یادرکھنا چاہئے کہ غلاموں کے یہ حقوق جن کا کسی قدرنمونہ او پر درج کیا گیا ہے محض سفارشی
رنگ نہیں رکھتے تھے بلکہ شرعی اور سیاسی احکام تھے اور حکومت اسلامی کی طرف سے نہایت سختی کے ساتھ
غلاموں کے حقوق کی نگرانی کی جاتی تھی.چنانچہ حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِي قَالَ كُنْتُ اَضْرِبُ غُلاَمًا بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي
إعْلَمُ اَبَا مَسْعُودٍ فَلَمُ اَفْهَمُ الصَّوَّاتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَى مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَيَقُولُ إِعْلَمُ اَبَا مَسْعُودٍ إِعْلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَالْقِيْتَ السَّوط
مِنْ يَدِى فَقَالَ إِعْلَمُ اَبَا مَسْعُودٍ إِنَّ اللهَ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَحُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ فَقَالَ أَمَّا لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلَفْحَتْكَ النَّارُ اَوْلَمَسَتُكَ النَّارُ
یعنی ابو مسعود بدری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی بات پر اپنے غلام کو مارا.اس وقت میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا دیکھوا بومسعود یہ کیا کرتے ہومگر
غصہ کی وجہ سے میں نے اس آواز کو نہ پہچانا اور غلام کو مارتا ہی گیا.اتنے میں وہ آواز میرے قریب
آگئی اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی آواز دیتے
ہوئے میری طرف بڑھتے چلے آرہے ہیں کہ دیکھو ابو مسعود یہ کیا کرتے ہو.آپ کو دیکھ کر
میری چھڑی میرے ہاتھ سے گر گئی اور آپ نے غصہ کی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا.ابو مسعود تمہارے سر پر ایک خدا ہے جو تمہارے متعلق اس سے بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے جو تم
اس غلام پر رکھتے ہو.میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! میں خدا کی خاطر اس غلام کو آزاد کرتا
ہوں.آپ نے فرمایا.اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہارے منہ کو جھلتی.“
مسلم کتاب الایمان باب ۳۵
66
Page 453
۴۳۸
پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ سَيِّدِى
زَوَّجَنِي أَمَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَابَالُ اَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ آمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا
إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
یعنی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک غلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ! میرے آقا نے اپنی لونڈی کے ساتھ میری شادی
کر دی تھی مگر اب وہ چاہتا ہے کہ ہمارے نکاح کو فسخ کر کے ہمیں ایک دوسرے سے جدا
کردے.آپ یہ بات سن کر غصہ کی حالت میں منبر پر چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہوکر
فرمایا.اے مسلمانو! یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی شادی کرتے ہو اور
پھر خود بخودا پنی مرضی سے ان میں علیحد گی کرانا چاہتے ہو؟ سن لو کہ ایسا ہر گز نہیں ہوسکتا.طلاق
دینے کا حق صرف خاوند کو ہے اور تم اپنے غلاموں کو طلاق پر مجبور نہیں کر سکتے.“
پھر حدیث میں آتا ہے:
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَذْهَبُ إِلَى الْحَوَالِى كُلَّ يَوْمٍ سَبْتٍ فَإِذَا وَجَدَ عَبْداً فِي عَمَلٍ
لا يُطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ
یعنی امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا یہ قاعدہ تھا کہ ہر ہفتہ مدینہ کے مضافات
میں جایا کرتے تھے اور جب انہیں کوئی ایسا غلام نظر آتا تھا جسے اس کی طاقت اور مناسبت کے
لحاظ سے زیادہ کام دیا گیا ہو تو حکماً اس کے کام میں تخفیف کر دیتے تھے.“
موجود الوقت غلاموں کی آزادی کے اب ہم اس سوال کے دوسرے حصہ کو لیتے ہیں
جو حاضر الوقت غلاموں کی آزادی کے ساتھ تعلق
متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رکھتا ہے اور جو اسلام اور بانی اسلام کا اصل
نصب العین تھا.سو جاننا چاہئے کہ اس کے متعلق اسلام میں دوطریق اختیار کئے گئے اول سفارشی طریق اور
دوسرے جبری طریق.اور ان دونوں طریقوں کے متحدہ اثر کے ماتحت آزادی کی تحریک کو تقویت پہنچائی
ابن ماجہ کتاب الطلاق
موطا امام مالک باب الامر بالرفق للمملوك
Page 454
۴۳۹
گئی.پہلے ہم سفارشی طریق کو لیتے ہیں.سب سے پہلے جبکہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی کی
ابتدا ہی تھی اور آپ مکہ میں مقیم تھے آپ پر یہ خدا کی وحی نازل ہوئی :
وَمَا ادريكَ مَا الْعَقَبَةُ ، فَكَ رَقَبَةٍ
یعنی ”اے رسول! کیا تم جانتے ہو کہ دین کے راستے میں ایک بڑی گھائی والی چڑھائی کون
سی ہے جس پر چڑھ کر انسان قرب الہی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے؟ اگر تم نہیں جانتے تو ہم بتاتے
ہیں کہ وہ غلام کا آزاد کرنا ہے.“
پھر فرمایا:
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ.....وَإِلَى الْمَالَ عَلى حُبّهِ ذَوِى الْقُرْبى وَالْيَتَى
وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ :
یعنی اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان خدا پر ایمان لائے...اور اس کی محبت
میں مال خرچ کرے رشتہ داروں پر قیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور غلاموں کے آزاد
کرنے پر.اور حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اِعْتَقَ رَقَبَةٌ مُسْلِمَةٌ اِعْتَقَ اللَّهُ
بِكُلِّ عُضْوِمِنْهُ عُضُوا مِنَ النَّارِ
یعنی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی
مسلمان غلام آزاد کرے گا.اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے کلی نجات عطا کر دے گا.“
پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِمُنِي
عَمَلاً يَدْخُلُنِى الْجَنَّةَ قَالَ لَانُ كُنْتَ اقْتَصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْاَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ اعْتِقِ
النِّسْمَةَ وَفَتِ الرَّقَبَةَ
یعنی ” براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
: سورة بلد : ۱۴۱۳
: سورة بقره : ۱۷۸
بخاری کتاب الايمان والنذور بیہقی شعب الایمان بحوالہ مشکواة كتاب العتق
Page 455
۴۴۰
خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا.یا رسول اللہ ! مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتا ئیں کہ بس میں اس
سے سیدھا جنت میں چلا جاؤں.آپ نے فرمایا تم نے لفظ تو مختصر کہے ہیں ،مگر بات بہت بڑی
پوچھی ہے.تم ایسا کرو کہ غلام کو آزاد کرو اور اگر خودا کیلئے آزاد نہ کر سکو تو دوسروں کے ساتھ
مل کر آزاد کرو.“
پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ
عِندَهُ وَلِيُدَةٌ فَعَلَمَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَادِيْبَهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا
فَلَهُ أَجْرَان
یعنی ابو بردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے
تھے کہ اگر کسی کے پاس ایک لونڈی ہو اور وہ بہت اچھی طرح اسے تعلیم دے اور بہت اچھی طرح
اس کی تربیت کرے اور پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ خود شادی کرے تو ایسا شخص خدا کے
حضور دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا.“
ان پُر زور سفارشات کے علاوہ اسلامی تعلیم میں بعض غلطیوں اور گناہوں کے کفارہ میں غلام کے
آزاد کرنے کا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے.جسے گویا سفارشی اور جبری طریق کے بین بین سمجھنا چاہئے.چنانچہ
اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے:
وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَّا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِةٍ إِلَا
أَنْ يَصَّدَّقُوا فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ :
یعنی " کوئی شخص کسی مومن کو یونہی غلطی سے قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان
غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے سوائے اس کے کہ اس کے ورثا
اسے یہ خون بہا خود بخود معاف کر دیں...اور اگر ایسے شخص کو کوئی غلام آزاد کرنے کے لئے نہ
ملے تو دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے.“
پھر فرماتا ہے:
فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُ وَلَكُمْ وَهُوَ مُؤْ مِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدُ
ل بخاری کتاب النکاح
: سورة النساء : ۹۳
Page 456
فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
۴۴۱
اگر مقتول ایسی قوم میں سے ہے جو مسلمانوں کی دشمن اور ان سے برسر پیکار ہے لیکن مقتول
خودمومن ہو تو پھر قاتل کی صرف یہ سزا ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے....اور اگر وہ کوئی
غلام نہ پاوے تو دوماہ کے لگاتا ر روزے رکھے “
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ -
:
اور اگر مقتول کسی ایسی قوم میں سے ہو جن کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہے تو خواہ
مقتول کا فر ہی ہو.اس کے قاتل کی سزا یہ ہے کہ وہ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرے اور
66
ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور اگر کوئی غلام نہ پائے تو دوماہ کے لگا تار روزے رکھے.“
پھر فرماتا ہے:
فَكَفَّارَتُه إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ
أوْ كِسْوَتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ
یعنی اگر کوئی شخص خدا کی قسم کھا کر پھر اسے توڑے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو اپنی
حیثیت کے مطابق کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو لباس عطا کرے یا ایک غلام آزاد کرے اور اگر
کوئی غلام نہ پائے تو تین دن کے روزے رکھے.“
پھر فرماتا ہے:
وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاشَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ...فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ
فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
یعنی جو لوگ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کا عہد کر لیتے ہیں لیکن پھر کسی وجہ سے انہی کی طرف
لوٹنا پڑتا ہے تو ان کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزادکر یں.اور اگر کوئی غلام نہ پائے تو ایسا شخص
دو مہینے کے لگا تار روزے رکھے....اور اگر روزوں کی طاقت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے.“
یہ وہ مختلف صورتیں ہیں جو اسلام نے کفارہ میں غلاموں کے آزاد کئے جانے کی بیان کی ہیں اور اسلام
۲۰ : سورة النساء : ۹۳
ے : سورۃ مائده : ۹۰
: سورة مجادله : ۵،۴
Page 457
۴۴۲
نے حسب عادت ان کے حالات کے اختلاف کوملحوظ رکھتے ہوئے دو دو تین تین مقابلہ کی صورتیں
تجویز کر کے ان میں مسلمانوں کو اختیار دے دیا ہے کہ جو صورت آسانی کے ساتھ اور بہتر طور پر اختیار کی
جاسکے اسے اختیار کر لیا جاوے اور کمال حکمت کے ساتھ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی غلام
کے آزاد کرنے کا ذکر ہے وہاں لازماً ساتھ ہی یہ الفاظ بھی زیادہ کر دیے ہیں کہ اگر کوئی غلام نہ پائے تو
پھر یہ یہ صورت اختیار کی جاوے.جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل منشاء یہ تھا کہ بالآخر غلامی کا
سلسلہ بالکل مفقود ہو جانا چاہئے.اس کے مقابلہ میں جب سورۃ مجادلہ کی آیت میں دو ماہ کے روزوں کے
مقابلہ کی صورت تجویز کی گئی ہے تو وہاں یہ الفاظ رکھے گئے ہیں کہ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر یوں کیا
جاوے.پس غلام کے آزاد کئے جانے کی صورت کے مقابلہ میں لازماً ان الفاظ کا آنا کہ اگر کوئی
غلام نہ پاوے اس بات میں کوئی شبہ نہیں چھوڑتا کہ اسلام کی انتہائی غرض موجود الوقت غلاموں کی
کلی آزادی تھی.پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَاقِ فِي كُسُوفِ
الشَّمس
یعنی ” اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حکم دیتے
تھے کہ سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کیا کریں.“
اب ہم جبری آزادی کے طریق کو لیتے ہیں.سو اس کے متعلق اسلام نے مختلف صورتیں تجویز کی
ہیں.چنانچہ حدیث میں آتا ہے:
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرَنِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي سَابِعُ اِخْوَةٍ لِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالَنَا خَادِمٌ غَيْرَ وَاحَدٍ فَعَمَدَ اَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَآمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعْتِقَهُ
یعنی سوید صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے اور ہمارے پاس صرف ایک غلام
تھا.ہم میں سے ایک کو کسی بات پر غصہ آیا تو اس نے اس غلام کو ایک طمانچہ رسید کر دیا.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم و علم ہوا تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس غلام کو آزاد کر دیں.“
بخاری کتاب العتق
: مسلم کتاب الایمان
Page 458
۴۴۳
یہی حدیث ابن عمر سے بھی مروی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مارے
اور پھر اسے آزاد کر دے تو اسے اس کے فعل کا کوئی ثواب نہیں ہوگا.کیونکہ غلام کا آزاد کیا جانا اسلام میں
مالک کے مارنے کے فعل کی سزا قرار پا چکا ہے.گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو جبری طور
پر آزاد کرنے کا ایک طریق یہ اختیار کیا کہ مالک کے لئے غلام کو مارنے کی سزا یہ مقرر کر دی کہ وہ اسے
فوراً آزاد کر دے.پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رِحْمٍ مُحَرَّمٍ
یعنی ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی
شخص کے قبضہ میں کوئی ایسا غلام آجاوے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے تو وہ غلام خود بخود آزاد
سمجھا جائے گا.پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اعْتَقَ شِرُكَالَّهُ فِي
مَمْلُوبٍ فَعَلَيْهِ عِتْقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِلَّا قُوَّمَ عَلَيْهِ
فَاسْتَسْعَىٰ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ _
یعنی ” ابن عمر اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص
کسی غلام کی ملکیت میں دوسروں کے ساتھ حصہ دار ہو اور وہ اپنے حصہ میں غلام کو آزاد کر دے تو
اس کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے دوسرے حصہ داروں کو بھی روپیہ دے کر غلام کو
کلیتہ آزاد کرا دے اور اگر اس کے پاس اتنا روپیہ نہ ہو تو پھر بھی غلام کو عملاً آزاد کر دیا جائے گا
تا کہ وہ خود اپنی کوشش سے بقیہ رقم پیدا کرے اور دوسرے مالکوں کو ادا کر کے کلی طور پر آزاد
ہو جاوے اور اس معاملہ میں غلام
کو ہر قسم کی سہولت دی جائے گی.“
پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ کے بعض غلام بھاگ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس آگئے جس پر مشرکوں نے آپ سے درخواست کی کہ وہ غلام انہیں واپس دے دیئے جائیں اور بعض
مسلم کتاب الایمان
: ابن ماجہ کتاب العتق
بخاری کتاب العتق
Page 459
۴۴۴
مسلمانوں نے بھی ان کی سفارش کی مگر اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے.چنانچہ
حدیث کے الفاظ یہ ہیں :
غَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سخت ناراض ہوئے اور غلاموں کے واپس کرنے
سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ تو خدا کے آزاد کردہ غلام ہیں.کیا میں انہیں پھر غلامی اور شرک کی
66
طرف لوٹا دوں.“
پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ آمَتُهُ مِنْهُ
فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرِمِنْهُ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ اُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وَإِنْ كَانَ سَقْط
یعنی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی
شخص اپنی لونڈی کے ساتھ رشتہ کرلے اور اسے آزاد نہ بھی کرے تو پھر بھی اگر اس لونڈی کے بطن
سے اس کے ہاں کوئی اولاد ہو جاوے تو اس کے بعد وہ لونڈی خود بخود آزاد سمجھی جائے گی اور ایک
روایت میں یوں ہے کہ اُمّ وَلَد بیوی بہر حال آزاد کبھی جائے گی خواہ بچہ کی پیدائش اسقاط کی
صورت میں ہی ہو.“
غلاموں کی آزادی کے لئے ایک مستقل انتظا تلف طریقے جبری آزادی کے تھے جو
اسلام نے قائم کئے.مگر ظاہر ہے کہ باوجود
ان جبری آزادیوں کے پھر بھی بہت سے غلام ایسے رہ جاتے تھے جو ان صورتوں میں سے کسی صورت سے
بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے اور دوسری طرف عام سفارشی رنگ میں ان کا آزادی حاصل کرنا یقینی نہیں تھا
اس لئے ضروری تھا کہ کوئی ایسا مستقل اور پختہ انتظام کیا جاتا جس سے یہ موجود الوقت غلام خود بخود آزادی
حاصل کرتے جاتے.سو اس کے متعلق اسلام نے وہ پُر از حکمت انتظام تجویز کیا جو مکا تبت کے نام سے
موسوم ہوتا ہے اور جس میں مالک اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر غلام اپنے حالات کے لحاظ سے (جس کا
فیصلہ حکومت یا عدالت کے ہاتھ میں ہوتا ہے نہ کہ مالک کے ہاتھ میں ) آزادی کی اہلیت کو پہنچ چکا ہو تو
کشف الغمہ باب امہات الاولاد
ل : ابو داؤد کتاب الجہاد : ابن ماجہ کتاب العتق
Page 460
۴۴۵
وہ اس سے مناسب رقم پیدا کرنے کی شرط کر کے اسے آزاد کر دے.چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم
وَاتُوهُمْ مِنْ قَالِ اللَّهِ الَّذِى اتُكُمْ
یعنی ”اے مسلمانو! تمہارے غلاموں میں سے جو غلام تم سے مکاتبت کا عہد کرنا چاہیں تمہارا
فرض ہے کہ ان سے مکاتبت کا عہد کر کے انہیں آزاد کر دو بشرطیکہ وہ آزادی کے اہل بن چکے ہوں
اور ایسی صورت میں تمہارا یہ بھی فرض ہے کہ اس مال میں سے انہیں بھی حصہ دو جو دراصل تو خدا کا
ہے مگر خدا نے اس مکاتبت کے نتیجہ میں تمہیں عطا کیا ہے.“
یہ آیت غلاموں کی جبری آزادی کے انتظام کا بنیادی پتھر ہے اور اس کے الفاظ بہت مختصر ہیں مگر اس
کے معانی نہایت وسیع اور نہایت وقیع ہیں.اس میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو غلام ان کے ساتھ
مکاتبت کا عہد کر کے آزاد ہونا چاہیں ان کا فرض ہے کہ انہیں آزاد کر دیں بشرطیکہ وہ آزادی کے قابل
بن چکے ہوں اور مکا تبت کے عہد سے یہ مراد ہے کہ غلام اور آقا کے درمیان یہ فیصلہ ہو جاوے کہ اگر
غلام اپنے آقا کو اس قدر رقم ادا کر دے گا تو وہ آزاد سمجھا جائے گا اور اس کا طریق یہ تھا کہ اس قسم کے
فیصلہ کے بعد غلام عملاً آزاد ہو جاتا تھا اور اس نیم آزادی کی حالت میں وہ کوئی کام یا پیشہ از قسم تجارت یا
صنعت و حرفت یا زراعت یا ملازمت وغیرہ اختیار کر کے مکاتبت کی رقم پوری کرنے کی کوشش کرتا
تھا اور جب یہ رقم پوری ہو جاتی تھی تو وہ کلی طور پر آزاد سمجھا جاتا تھا اور مکا تبت کی رقم گومالک کے تصرف
میں سمجھی جاتی تھی مگر مالک کا یہ فرض تھا کہ اس میں سے مناسب حصہ غلام کو بھی دے.یہ انتظام ایسا
مبارک اور پر حکمت تھا کہ اس کے نتیجہ میں غلاموں میں سے اہل لوگ نہ صرف خود بخو د بطور حق کے آزاد
ہوتے چلے جاتے تھے بلکہ بوجہ اس کے کہ انہیں مکاتبت کی رقم پوری کرنے کے لئے کسی آزاد نہ کام میں
پڑنا پڑتا تھا اور ایک سول معاہدہ کی ذمہ داری برداشت کرنی پڑتی تھی.ان میں آزاد زندگی گزار نے اور
ملک کے مفید شہری بننے کی قابلیت بھی پیدا ہو جاتی تھی.مکاتبت کا یہ انتظام مالک کی مرضی پر منحصر نہیں تھا بلکہ جبری تھا.یعنی غلام کی طرف سے مکاتبت کا
مطالبہ ہونے پر مالک کو انکار کا حق نہیں ہوتا اور یہ کام عدالت یا حکومت کا تھا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے
کہ آیا غلام آزادی کے قابل ہو چکا ہے یا نہیں.چنانچہ روایت آتی ہے کہ :
ا: سورة نور : ۳۴
Page 461
۴۴۶
إِنَّ سِيرِينَ سَأَلَ اَنَسًا الْمُكَاتِبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَابِي فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ كَاتِبُهُ فَأَبَى
فَضَرَبَهُ بِالدُّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيْهِمْ خَيْراً فَكَاتَبَهُ
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس کا ایک غلام تھا جس کا نام سیرین تھا اس نے انس کے
ساتھ مکاتبت کرنی چاہی مگر انس نے یہ خیال کر کے کہ میرے پاس بہت روپیہ ہے مجھے مکاتبت کے روپے
کی ضرورت نہیں ہے.مکاتبت سے انکار کر دیا.اس پر سیرین نے حضرت عمر کے پاس حضرت انسؓ کی
شکایت کی.حضرت عمرؓ نے سیرین کی شکایت سن کر انس کو حکم دیا کہ وہ مکا تبت کریں ،لیکن انس نے پھر بھی
نہ مانا.جس پر حضرت عمرؓ نے انس کو ڈرہ سے مارا اور یہ قرآنی آیت سنائی کہ اے مسلمانو ! اگر تمہارے
غلام تمہارے ساتھ مکاتبت کرنا چاہیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے ساتھ مکا تبت کرو.اس پر انس نے
سیرین سے مکاتبت کا عہد کر لیا.“
مکاتبت کی فرضیت کا دار ومدار اس بات پر تھا کہ آیا کوئی غلام آزادی حاصل کرنے کا اہل بن چکا ہے
یا نہیں.چنانچہ بیٹی بن کثیر سے روایت آتی ہے کہ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْراً قَالَ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ حِرْفَةً وَلا تُرْسِلُوهُمْ كَلَّا عَلَى النَّاسِ
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن شریف میں آتا ہے کہ اگر تم
غلاموں میں بھلائی پاؤ تو تمہارا فرض ہے کہ تم مکاتبت سے انکار نہ کرو.اس میں بھلائی سے مراد
پیشہ وغیرہ کی اہلیت ہے یعنی مقصود یہ ہے کہ ایسے غلاموں کے ساتھ مکا تبت ضروری ہو جاتی ہے
جو کوئی پیشہ یا کام وغیرہ جانتے ہوں یا جلد سیکھ سکتے ہوں تا کہ وہ آزادی حاصل کرنے کے بعد
سوسائٹی پر کسی قسم کے بوجھ کا باعث نہ بنیں.“
اور یہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ اس بات
کا فیصلہ کہ کوئی غلام اس بات کی اہلیت کو پہنچا ہے یا نہیں حکومت
کے ہاتھ میں تھا نہ کہ مالک کی مرضی پر.یہ حدیث اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ دراصل اسلامی تعلیم کا
اصل منشاء یہی تھا کہ موجود الوقت غلاموں کی حالت کو بہتر بنا کر انہیں آزادی کے قابل بنایا جاوے اور جوں
جوں یہ غلام آزادی کے قابل ہوتے جائیں توں توں انہیں آزادی ملتی جاوے.یہ مکاتبت کا طریق چونکہ غلاموں کی آزادی کے انتظام کا بنیادی پتھر تھا اس لئے اسلام میں اسے
بخاری کتاب المكاتب
ابوداؤد بحوالہ تفسیر ابن کثیر زیر
تفسیر آیت مکاتبت
Page 462
۴۴۷
نہایت پسندیدہ سمجھا گیا ہے.چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَهُ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ
الْمُكَاتِبُ الَّذِى يُرِيدُ الْآدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِى يُرِيدُ الْعِفَافَ وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.یعنی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تین قسم
کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کو اپنے اوپر ایک حق کے طور پر قرار دے لیا
ہے.اوّل مکاتب غلام جو اپنی مکاتبت کی رقم کی ادائیگی کی فکر میں ہے.دوسرے وہ شادی
66
کرنے والا شخص جو اپنی عفت کے بچانے کی نیت رکھتا ہے اور تیسرے مجاہد فی سبیل اللہ.“
غلاموں کی آزادی کی تحریک صرف افراد تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ اسلامی سلطنت کا بھی یہ فرض قرار
دیا گیا تھا کہ وہ قومی بیت المال میں سے ایک معتدبہ حصہ غلاموں کے آزاد کرانے میں صرف
کرے.چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
إِنَّمَا الصَّدَقُتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَ الْعَرِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
یعنی زکوۃ کے اموال فقراء اور مساکین پر خرچ ہونے چاہئیں اور محکمہ زکوۃ کے عاملین
پر اور کمزور نومسلموں پر اور غلاموں کے آزاد کرنے میں.اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی میں
اور اشاعت دین کے لئے اور مسافروں کو آرام پہنچانے کے لئے.یہ ایک فرض ہے جو اللہ تعالیٰ
نے مقرر کیا.“
اس آیت کی رو سے اسلامی سلطنت کا فرض مقر ر کیا گیا ہے کہ وہ زکوۃ کے محاصل میں سے غلاموں کی
آزادی پر روپیہ خرچ کرے.آزاد شدہ غلاموں کے متعلق تعلیم غلاموں کی آزادی کے اس انتظام میں اس بات
کو بھی مدنظر
رکھا گیا تھا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد شدہ غلام بالکل
بے سہارا اور بے یار و مددگار نہ رہیں.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ مالک
اور آزاد شدہ غلام کے درمیان ایک قسم کا رشتہ اخوت مستقل طور پر قائم رہے.چنانچہ آپ کے حکم کے
ماتحت مالک اور آزاد شدہ غلام ایک دوسرے کے ”مولیٰ یعنی دوست اور مددگار کہلاتے تھے تا کہ آقا اور
ل ترمذی ونسائی وابن ماجہ بحوالہ مشکوۃ کتاب النکاح
ے : سورة توبه : ۶۰
Page 463
۴۴۸
غلام دونوں کے دلوں میں یہ احساس رہے کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور بوقت ضرورت ہم
نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے اسی مصلحت کے ماتحت آزادشدہ غلام اور مالک کو ایک دوسرے
کے متعلق حق موروثیت بھی عطا کیا گیا تھا.یعنی اگر غلام بے وارث مرتا تھا تو اس کا ترکہ اس کے سابقہ
آقا کو جاتا تھا اور اگر مالک بے وارث رہ جاتا تھا تو اس کا ورثہ اس کے آزاد کردہ غلام کو ملتا تھا.چنانچہ حدیث میں آتا ہے:
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوِلَاءَ لِمَنِ اعْتَقَ ۚ وَعَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَدَعَ وَارِثًا إِلَّا
عَبْدًا هُوَ اعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ
یعنی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی
آزاد شدہ غلام لا وارث مر جاوے تو اس کا ترکہ اس کے سابق مالک کو ملے گا اور ابن عباس سے
مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ایسی حالت میں مرگیا کہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا.البتہ اس
کا ایک آزادشدہ غلام تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترکہ اس کے آزادشدہ غلام کو
عطا فر ما دیا.“
چونکہ اس حق موروثیت کی بنیاد مالی اور اقتصادی خیالات پر مبنی نہیں تھی بلکہ اصل منشا مالک اور
آزادشدہ غلام کے تعلق کو قائم رکھنا تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا کہ یہ حق
موروثیت کسی صورت میں بھی بیچ یا ہبہ وغیرہ نہیں ہو سکتا.چنانچہ ابن عمر سے روایت آتی ہے کہ:
نَهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوِلَاءِ وَهِبَتِهِ - =
یعنی " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد شدہ غلام اور آقا کے حق موروث کی خرید وفروخت
اور اس کے ہبہ وغیرہ سے منع فرمایا ہے:
پھر آزاد شدہ غلاموں کی عزت واحترام کے قیام کے لئے حدیث میں آتا ہے:
عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرٍ واَنَّ اَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبَلَالٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا
وَاللهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوقَ اللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوّ اللَّهِ مَأَخَذَهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ اَتَقُولُونَ هَذَا
: بخاری کتاب العتق
بخاری کتاب العتق
ترمذی ابواب الفرائض و ابودا و دوابن ماجہ بحوالہ مشکوة
Page 464
۴۴۹
لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ
أَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ فَأَتَاهُمْ أَبُوْبَكْرٍ فَقَالَ يَا إِخْوَتَاهُ
أَغَضَبْتُكُمْ قَالُوا لَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَخِي يا
یعنی ایک دفعہ سلمان اور صہیب اور بلال وغیرہ جو آزاد شدہ غلام تھے ایک جگہ بیٹھے ہوئے
تھے ان کے سامنے سے ابوسفیان گزرا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ خدا کا دشمن خدائی تلوار سے
بچ گیا ہے.حضرت ابو بکر نے ان کی یہ بات سنی تو انہیں فہمائش کی اور کہا کہ کیا تم قریش کے
سردار کے متعلق ایسی بات کہتے ہو؟ اس کے بعد ابو بکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور آپ سے سارا ماجرا عرض کیا.آپ نے فرمایا ابوبکر اتم نے بلال وغیرہ کو کہیں
ناراض تو نہیں کر دیا ؟ اگر تم نے انہیں ناراض کیا ہے تو ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی
ہے.حضرت ابوبکر فور ابلال وغیرہ کے پاس واپس آئے اور کہا بھائیو! تم میری بات پر ناراض تو
نہیں ہوئے.انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم ناراض نہیں ہوئے.فکر نہ کرو.“
مسلمانوں نے غلاموں کی آزادی کی تعلیم پر کس طرح عمل کیا اب صرف یہ سوال رہ
جاتا ہے کہ ان سفارشات
اوران کفارہ جات اور جبری آزادیوں اور اس انتظام مکاتبت کے نتیجے میں غلاموں کی آزادی عملاً بھی
وقوع میں آئی یا نہیں ؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اس زمانہ میں غلام نہایت
کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے.حتی کہ بعض ممالک میں بعض اوقات غلاموں کی تعداد اصل آبادی
سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی.ہے پس اس غیر متناہی ذخیرہ کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور نہ ہی یہ سارے
غلام محدود اسلامی سلطنت اور محدودتر مسلمان مالکوں کے ماتحت تھے.پس لازماًیہ آزادی کی تحریک آہستہ
آہستہ ہی چل سکتی تھی لیکن تاریخ سے ثابت ہے کہ جہاں تک صحابہ اور ان کے متبعین کی کوشش کا تعلق
تھا انہوں نے غلاموں کے آزاد کرنے اور آزاد کرانے میں اپنی پوری توجہ اور پوری سعی سے کام لیا اور وہ
نمونہ دکھایا جو یقیناً تاریخ عالم میں اپنی نظیر نہیں رکھتا.چنانچہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان
نہ صرف اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے غلاموں کو کثرت سے آزاد کرتے رہتے تھے بلکہ خاص اس نیت اور اس
ارادے سے غلام خرید تے بھی تھے کہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں اور اس طرح بے شمار غلام مسلمانوں کی
نے مسلم باب فضائل سلمان و صہیب و بلال
انسائیکلو پیڈیا برٹینی کا بحث غلامی
Page 465
۴۵۰
مساعی جمیلہ سے داغ غلامی سے نجات پاگئے.چنانچہ مندرجہ ذیل فہرست جو یقیناً مکمل نہیں ہے اور جس
میں نمونہ کے طور پر صرف چند صحابیوں کا نام لیا گیا ہے ہمارے اس دعوی کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے.سُبُلُ السَّلام میں روایت آتی ہے کہ :
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ نے
حضرت عباس نے
حکیم بن حزام نے
تریسٹھ
غلام آزاد کئے
سٹر سٹھ غلام آزاد کئے
ستر
غلام آزاد کئے
یکصد
غلام آزاد کئے
عبداللہ بن عمر نے
عبدالرحمن بن عوف نے
ایک ہزار غلام آزاد کئے
تین ہزار غلام آزاد کئے
حضرت عثمان بن عفان نے
ہیں
غلام آزاد کئے صرف ایک دن میں جو ان کی
شہادت کا دن تھا ؤ الا ان کی
مجموعی تعداد بہت زیادہ تھی
ذوالکلاع الحمیری نے
آٹھ ہزار غلام آزاد کئے صرف ایک دن میں
میزان
انتالیس ہزار تین سو بیس لے
جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے اس روایت میں بطور نمونہ صرف چند صحابہ کا نام لیا گیا ہے اور اگر اسی
نسبت سے دوسرے کثیر التعداد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے متعلق قیاس کیا جاوے تو یہ تعداد یقیناً
کروڑوں سے اوپر پہنچتی ہے لیکن حق یہ ہے کہ اس روایت میں جو تعداد مذکورہ بالا صحابہ کے آزاد کردہ
غلاموں کی بیان کی گئی ہے وہ بھی درست نہیں بلکہ اصل تعداد اس سے بہت زیادہ ہے.مثلاً حضرت عائشہ
کے متعلق ایک روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے صرف ایک موقع پر چالیس غلام آزاد کئے تھے.نے
اور دوسری روایت سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا یہ طریق تھا کہ وہ نہایت کثرت کے ساتھ غلام آزاد کیا کرتی
تھیں.پس ان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ انہوں نے ساری عمر میں صرف ستاسٹھ غلام آزاد کئے تھے یقیناً
درست نہیں.اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تعداد بتائی گئی ہے وہ گو آپ کی ذاتی
حیثیت میں درست ہو کیونکہ آپ کی ذاتی مالی حالت اچھی نہیں تھی اور آپ ان احکامات کے جاری ہونے
: سُبل السلام شرح بلوغ المرام كتاب العتق : بخاری کتاب الادب باب الحجرت
Page 466
۴۵۱
کے بعد زندہ بھی بہت تھوڑا عرصہ رہے تھے ، لیکن یقیناً اس تعداد میں وہ غلام شامل نہیں ہیں جو آپ نے
اسلامی حکومت کے ہیڈ ہونے کی حیثیت میں آزاد کئے اور جن کی تعداد بہت زیادہ تھی.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے متعلق ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہئے اور وہ یہ کہ آپ کے متعلق بہت سی روایات سے ثابت
ہے کہ کبھی کوئی ایک غلام بھی آپ کے قبضہ میں نہیں آیا کہ اسے آپ نے آزاد نہ کر دیا ہو.چنانچہ مندرجہ
ذیل روایت میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے.عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَخِى جُوَيْرِيَةَ أَمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَاراً وَلَا عَبْداً وَلَا اَمَةً
یعنی " عمرو بن الحارث سے روایت ہے جو ام المؤمنین جویریہ کے حقیقی بھائی اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت کوئی درہم
کوئی دینار کوئی غلام اور کوئی لونڈی اپنے پیچھے نہیں چھوڑی.“
الغرض اسلام کی یہ تعلیم جو اس نے غلاموں کے متعلق دی صرف کاغذوں کی زینت نہیں تھی بلکہ یہ تعلیم
اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی طریق معاشرت کا ایک ضروری جزو بن گئی تھی اور افراد و حکومت دونوں
پورے شوق کے ساتھ اس پر عمل پیرا تھے.آزاد شدہ غلاموں کے لئے تمام یہ بتایا جا چکا ہے کہ غلاموں کو آزادی اس اطمینان کے بعد دی
جاتی تھی کہ وہ اخلاق وعادات اور روزی کمانے کی اہلیت
ترقی کے دروازے کھلے تھے کے لحاظ سے آزادی کے قابل ہوجائیں.اب ہم یہ بتانا
چاہتے ہیں کہ جو غلام آزاد کئے جاتے تھے وہ واقعی مفید شہری بن جاتے تھے اور اسلامی سوسائٹی میں ویسے ہی
معزز و مکرم سمجھے جاتے تھے جیسے کہ دوسرے لوگ.بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ لوگوں
کے پرانے خیالات کی اصلاح کی غرض سے آپ غلاموں اور آزاد شدہ غلاموں میں سے قابل لوگوں کی
تعظیم و تکریم کا خیال دوسرے لوگوں کی نسبت بھی زیادہ رکھتے تھے.چنانچہ آپ نے بہت سے موقعوں پر
اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اور ان کے لڑکے اسامہ بن زید کو جنگی مہموں میں امیر مقرر فرمایا اور
بڑے بڑے صاحب عزت اور جلیل القدر صحابیوں کو ان کے ماتحت رکھا اور جب نا سمجھ لوگوں نے اپنے
پرانے خیالات کی بنا پر آپ کے اس فعل پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا :
ل بخاری بروایت مشکوۃ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم
Page 467
۴۵۲
إِنْ تَطْعِنُوا فِي أَمَارَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ تَطْعِنُونَ فِي اَمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ
لَخَلِيْقًا لِلَا مَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ -
یعنی " تم لوگوں نے اسامہ کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا ہے اور اس سے پہلے تم اس
کے باپ زید کی امارت پر بھی طعن کر چکے ہوں، مگر خدا کی قسم جس طرح زید امارت کا حق دار اور اہل
تھا اور میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اسی طرح اسامہ بھی امارت کا اہل ہے اور میرے
محبوب ترین لوگوں میں سے ہے.“
پھر اس سے بڑھ کر کیا ہو گا کہ آپ نے اپنی حقیقی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جحش کو زید بن حارثہ سے
بیاہ دیا اور عجیب کرشمہ یہ ہے کہ سارے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام مذکور ہوا ہے تو وہ یہی زید بن حارثہ
ہیں..پھر علم وفضل میں بھی بعض آزاد شدہ غلاموں نے بہت بڑا رتبہ حاصل کیا.چنانچہ سالم بن معقل
مولی ابی حذیفہ خاص الخاص علماء صحابہ میں سے سمجھتے جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف
کی تعلیم کے لئے جن چار صحابیوں کو مقرر فرمایا تھا ان میں سے ایک سالم بھی تھے.اور تقویٰ وطہارت کی
وجہ سے تعظیم و تکریم کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر بلال کے متعلق اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ ہمارا سردار ہے.پھر صحابہ کے بعد بھی بعض آزاد شدہ غلاموں نے اسلامی سوسائٹی میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا.چنانچہ
عطاء بن ابی رباح ، مجاہد بن جبیر، نافع مولیٰ ابن عمر اور موسیٰ بن عقبہ بزرگ ترین تابعین میں سے سمجھے
جاتے تھے.جن کے سامنے بڑے بڑے جلیل القدر لوگ زانوئے تلمیذی طے کرتے تھے.تمام غلاموں کو یکلخت کیوں نہ آزاد کر دیا گیا پیشتر اس کے کہ ہم اس بحث کو ختم کریں اس
سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ جب اسلام
غلاموں کی آزادی اور رستگاری کا پیغام لے کر آیا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ تمام حاضر الوقت
غلاموں کو یکلخت حکماً آزاد کروا دیا ؟ سو اس کا مختصر اور سادہ جواب تو صرف اس قدر ہے کہ آپ نے
اس لئے ایسا نہیں کیا کہ آپ غلاموں کے حقیقی دوست تھے اور آپ کا کام اصلاح کرنا تھا نہ کہ نمائش.پس
آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو بظاہر تو دوستی کا رنگ رکھتا ہو لیکن حقیقتا وہ غلاموں کے لئے نقصان دہ
اور ملک کی ترقی اور تمدن کے لئے ضرر رساں ہو.ہر ایک عقل مند شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کے حالات
بخاری کتاب فضائل اصحاب
سے ، بخاری کتاب فضائل
سورۃ احزاب : ۳۸
۵ : تہذیب التہذیب
Page 468
۴۵۳
کے ماتحت لاکھوں غلاموں کا یکلخت آزاد ہو جانا غلاموں کو ایک ایسی بے سہارا اور غیر محفوظ حالت میں چھوڑ
دیتا جو ان کے لئے کئی لحاظ سے خطرناک ہو سکتی تھی اور اس زمانہ کے حالات کے ماتحت اس فوری اور
عالمگیر آزادی کا نتیجہ یقیناً یہ ہوتا کہ ان آزاد شدہ غلاموں میں سے اگر ایک حصہ غربت کی حالت میں فاقوں
سے مرتا تو دوسرا حصہ بیکاری اور ارتکاب جرائم کی طرف مائل ہو کر اپنی اخلاقی تباہی اور ملک وقوم کی بے
چینی اور بدامنی کا باعث بن جاتا.انقلابی تجاویز خواہ بعض اوقات جذباتی رنگ میں کیسی ہی دل خوشکن نظر
آئیں مگر حقیقتاً وہ اکثر صورتوں میں نفع مند ثابت نہیں ہوتیں بلکہ بعض صورتوں میں تو ان سے افراد کے
عادات و خصائل اور قوم کی اجتماعی زندگی اور تمدن پر خطرناک اثر پڑتا ہے.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جو ایک حقیقی مصلح تھے اور غلاموں کے لئے وہ کام کرنا چاہتے تھے جو ان کے لئے فی الواقع مفید اور بابرکت
ہو.ایسے رستہ پر قدم زن نہیں ہوئے جو عرب کی سوسائٹی میں ایک تباہ کن زلزلہ پیدا کرنے والا ثابت
ہوتا اور غلاموں کو اس سے بجائے فائدہ کے نقصان پہنچتا.خوب سوچ لو کہ اس زمانہ کے حالات کے
ماتحت لاکھوں غلاموں کو بغیر کسی دوراندیشانہ انتظام کے یکلخت آزاد کر دینے کے یقیناً یہ معنے تھے کہ ان
غلاموں کی دنیا بھی تباہ ہوتی اور دین بھی.یعنی دنیا کے لحاظ سے ان میں سے اکثر نہ صرف بالکل بے سہارا
اور بے ذریعہ معاش رہ جاتے.بلکہ ان کے لئے کسب سیکھنے کے موقعے بھی میسر نہ رہتے اور دینی لحاظ سے
ان کی یہ فوری اور عالمگیر آزادی ان کے اخلاق و عادات پر ایک نہایت ضرر رساں اثر پیدا کرتی
خصوصاً جبکہ ایک بہت لمبے عرصے کی ظالمانہ غلامی کے نتیجہ میں ان کے اندر دنائت اور سنگدلی اور اسی قسم
کے دوسرے مذموم اخلاق پیدا ہو چکے تھے جو فوری آزادی کے نتیجہ میں نہ معلوم کس رستے پر پڑ کر کیا کیا
رنگ لاتے اور اس عالمگیر آزادی کے نتیجے میں جو دوسرے مضر اثرات سوسائٹی پر پڑ سکتے تھے وہ مزید براں
تھے.پس اسلام نے کمال دانش مندی سے یہ تجویز اختیار فرمائی کہ ایک طرف تو آئندہ کے لئے غلامی کے
ظالمانہ طریقوں کو بند کر کے اس حلقہ کی مزید وسعت کو روک دیا جیسا کہ آگے چل کر اس کی بحث آئے گی
اور دوسری طرف وقتی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے موجود الوقت غلاموں کی اخلاقی اور معاشرتی اور
اقتصادی اصلاح و بہبودی کے لئے عملی تدابیر اختیار فرمائیں اور ساتھ ہی یہ انتظام فرمایا کہ جوں جوں یہ
غلام آزاد زندگی کو مفید طور پر بسر کرنے کے قابل ہوتے جائیں توں توں وہ لازماً آزاد ہوتے جائیں
اور یہی وہ حقیقی اصلاح کا طریق تھا جو اس زمانے کے حالات کے ماتحت بہترین نتائج کی امید کے ساتھ
اختیار کیا جا سکتا تھا بلکہ اس انتظام کا تفصیلی مطالعہ اس بات میں ذرا بھی شک نہیں رہنے دیتا کہ یہ ایک
Page 469
۴۵۴
عدیم المثال نظام تھا جس کی نظیر نہ تو اس سے پہلے کسی زمانہ میں نظر آتی ہے اور نہ اس کے بعد آج تک ایسا
نمونہ کسی قوم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے.اگر اس جگہ کسی کو یہ شبہ پیدا ہو ہ گزشتہ صدی کے دوران بہت سے یورپین اور امریکن مصلح ایسے
گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو غلاموں کی آزادی کی تحریک میں گویا وقف کر دیا تھا اور ان کی
کوششوں کے نتیجے میں دنیا کے بیشتر ممالک میں غلامی کا سلسلہ یکلخت منسوخ ہو گیا تھا.مثلاً ابراہام لنکن نے
جو اپنے وقت میں امریکہ کی جمہوری سلطنت کا صدر تھا.امریکہ کے لاکھوں حبشی غلاموں کو یکلخت آزادی
دلا دی اور اس فوری اور عالمگیر آزادی کا کوئی برا نتیجہ نہیں نکلا بلکہ ابراہام لنکن کی یہ خدمت انتہائی تحسین کی
نظر سے دیکھی جاتی ہے.تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو آج سے چودہ سوسال قبل کے زمانہ اور آج کے
زمانہ کے حالات میں زمین و آسمان کا اختلاف ہے اور چونکہ اسلام کی یہ تعلیم جو اس زمانہ کے غلاموں کی
تدریجی آزادی کے متعلق دی گئی تھی اس زمانہ کے حالات کے ماتحت تھی اور مستقل تعلیم اسلام کی اس
بارے میں اور تھی جن کا ذکر آگے آتا ہے اس لئے عقلاً یہ مقابلہ کسی صورت درست نہیں سمجھا جاسکتا.پس
اگر موجودہ زمانہ کے حالات میں فوری اور عالمگیر آزادی مضر ثابت نہیں ہوئی تو اس سے لازمی طور پر یہ نتیجہ
نہیں نکلتا کہ آج سے پہلے زمانوں اور آج کی نسبت دوسری قسم کے حالات میں بھی یہ طریق ضرر رساں
ثابت نہ ہوتا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غلاموں کی اخلاقی اور معاشرتی حالت نہایت درجہ
پست تھی اور دوسری طرف دنیا کا تہذیب و تمدن بھی اس تہذیب و تمدن سے بالکل جدا تھا جو آج کل دنیا
میں پایا جاتا ہے.پس اس زمانہ کے حالات کے ماتحت یہی مناسب تھا کہ بجائے فوری اور عالمگیر آزادی
کے تدریجی آزادی کے طریق کو اختیار کیا جاتا اور نہ نتیجہ بجائے مفید ہونے کے یقیناً مضر ہونا تھا.یہ ایک
اصولی جواب ہے جو اس اعتراض کا دیا جا سکتا ہے.مگر حق یہ ہے کہ جو تجاویز اسلام نے اختیار کیں وہ
بہر حال زیادہ مفید اور نفع مند تھیں اور ہر غیر متعصب شخص جو ٹھنڈے طور پر اس مسئلہ کے متعلق غور کرے گا وہ
اس نتیجہ پر پہنچے گا جو ہم نے بیان کیا ہے.حضرت مسیح ناصری کا ایک نہایت سچا مقولہ ہے کہ درخت اپنے
پھل سے پہچانا جاتا ہے.پس ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ان دونوں قسم کے طریقوں میں سے کس طریق کے
نتائج زیادہ مفید اور زیادہ نفع مند ثابت ہوئے ہیں.آیا اس طریق کے جو اسلام نے آج سے چودہ سوسال
قبل اختیار کیا تھا یا اس طریق کے جو موجودہ زمانہ میں بعض یورپین اور امریکن مصلحین نے اختیار کیا ہے؟
اس جگہ ہم کسی تفصیلی بحث میں داخل نہیں ہو سکتے ، صرف موٹے طور پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ہر دو
Page 470
۴۵۵
طریقوں کے نتائج کی نسبتی خوبی کا دو طرح پر امتحان کیا جا سکتا ہے.اوّل اس پہلو سے کہ ان طریقوں میں سے کس طریقہ کے نتیجہ میں زیادہ حقیقی آزادی قائم ہوئی.دوسرے اس پہلو سے کہ ان میں سے کس طریقہ کے نتیجہ میں آزاد شدہ غلاموں نے زیادہ ترقی کی.اور ہم دعوئی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے وہ طریقہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے آج سے چودہ سو برس قبل اختیار کیا تھا اس طریق سے بدرجہا بہتر تھا ، جو بعض مغربی مصلحین نے
اس زمانہ میں اختیار کیا ہے.ظاہر ہے کہ صرف نام کے طور پر کسی غلام کو آزاد کر دینا مگر غلامی کی اصل روح
کونہ مارنا ہرگز حقیقی آزادی کا فعل نہیں سمجھا جا سکتا لیکن غور سے دیکھا جائے تو جو اصلاح مغربی مصلحین
نے کی ہے وہ کسی صورت میں بھی اس نام نہا د اصلاح سے بڑھ کر نہیں.بیشک انہوں نے لاکھوں غلاموں کو
آزاد کیا اور یکلخت حکماً آزاد کیا، مگر وہ غلامی کی روح کو نہیں مار سکے بلکہ اس آزادی کے بعد بھی آزاد کرنے
والوں اور آئندہ آزاد ہونے والوں کے دل و دماغ میں غلام بنانے اور غلام بننے کی روح اسی طرح زندہ
رہی.جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقی طور پر غلامی بھی نہ مٹی اور آقاؤں اور غلاموں کے تعلقات بھی سخت کشیدہ
ہو گئے.امریکہ کی ہی مثال لے لو.بیشک ریاستہائے متحدہ میں بظاہر لاکھوں حبشی غلاموں نے یکلخت
آزادی حاصل کر لی مگر قطع نظر اس کے کہ اس عالمگیر آزادی کی وجہ سے ملک ایک خطر ناک خانہ جنگی کی
آگ سے شعلہ بار ہو گیا تھا.کیا اس وقت امریکہ کا حبشی غلام واقعی آزاد ہو گیا تھا؟ بلکہ ہم پوچھتے ہیں کہ
کیا اس وقت تک بھی ملک کا کوئی قانون امریکہ کے حبشی غلام کو حقیقی آزادی دلا سکا ہے؟ کیا امریکہ کا گورا
آدمی اپنے آزاد کردہ حبشی غلام کو آج تک دنیا کے بدترین غلاموں سے عملاً بدتر نہیں سمجھتا ؟ پھر کیا یہ آزاد
شدہ حبشی اپنے آپ کو حقیقی طور پر امریکہ میں آزاد سمجھتا ہے؟ یقیناً امریکہ میں آزاد کرنے والے گورے
لوگوں اور آزاد ہونے والے کالے حبشیوں کے تعلقات بین الاقوام تعلقات کی بدترین مثال ہیں جو اس
وقت دنیا میں پائی جاتی ہے اور یہ حالت اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان غلاموں کے آزاد کرنے میں وہ طریق
اختیار کیا گیا ہے جس سے غلام لوگ نام کو تو بیشک آزاد ہو گئے مگر ان کو حقیقی آزادی نہیں مل سکی اور آزاد
کرنے والوں اور آزاد ہونے والوں کی ذہنیتوں میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی.اس کے مقابلہ میں اسلامی
طریق پر جولوگ آزاد کئے گئے وہ گو تدریجی طور پر آزاد ہوئے مگر آزاد ہونے کے بعد وہ حقیقتا آزاد
تھے.یعنی ان کے جسم بھی آزاد تھے ، ان کی روحیں بھی آزاد تھیں ، ان کے خیالات بھی آزاد تھے، ان کی
ذہنتیں بھی آزاد تھیں اور ان آزاد شدہ غلاموں اور ان کے آزاد کرنے والے لوگوں کے درمیان وہ
Page 471
۴۵۶
محبت واخلاص کے تعلقات قائم ہو گئے تھے کہ آج کی حقیقی اخوت بھی ان کے سامنے شرماتی ہے.میں جب
اس زمانہ کے امریکن حبشی نام اور آج سے چودہ سو سال قبل کے عربی حبشی بلال کے حالات پر نگاہ کرتا ہوں
تو ایک عجیب منظر نظر آتا ہے.باوجود اس کے کہ یہ دونوں شخص حبشی ہیں اور دونوں آزاد شدہ غلام
ہیں.عربی غلام ( یعنی بلال ) جب بادشاہ وقت ( یعنی عمر بن الخطاب) سے ملنے کے لئے جاتا ہے تو باوجود
اس کے کہ اس وقت بڑے بڑے رؤساء عرب بادشاہ کی ملاقات کے انتظار میں دروازے پر بیٹھے ہوتے
ہیں.بادشاہ وقت بلال کی خبر پاکر ان رؤساء عرب کو جو وہ بھی مسلمان ہی تھے نہیں بلاتا اور بلال کو فور ابلا
لیتا ہے اور جب بلال ملاقات سے فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان رؤساء عرب کی باری آتی
ہے اور جب اس بادشاہ کی مجلس میں بلال کا ذکر آتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے ”بلال ہمارا سردار اے ہے.لیکن
اس کے مقابلہ میں امریکہ کے آزاد شدہ حبشی نام کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے آزاد کرنے
والوں کے پاؤں کی ٹھوکریں کھاتا اور مجلسوں میں ذلت کی جگہوں میں بٹھایا جاتا اور ہر قسم کے مظالم
ہتا اور دم نہیں مارسکتا.یہ اختلاف کیوں ہے؟ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام نے جوطریق غلاموں کی
آزادی کا اختیار کیا ، وہ حقیقی اصلاح کا طریق تھا.پس اس کے نتیجہ میں حقیقی آزادی پیدا ہوئی لیکن مغربی
مصلحین کی اصلاح ناقص اور ان کا طریق غلط تھا.پس اس کے نتیجہ میں بیشک نام کو تو آزادی مل گئی مگر
غلامی کی روح پر موت نہیں آئی اور ذمنیتیں وہی کی وہی رہیں.دوسرا طریق اس سوال پر غور کرنے کا یہ ہے کہ یہ دیکھا جاوے کہ ان طریقوں میں سے کس طریق
کے نتیجہ میں آزاد شدہ غلاموں نے زیادہ ترقی کی.سو مذکورہ بالا بحث کے بعد اس سوال کا جواب بھی مشکل
نہیں رہتا.کیونکہ طبعا وہی رستہ غلاموں کی زیادہ ترقی کا ہونا چاہئے ، جس میں انہیں زیادہ حقیقی آزادی
حاصل ہو.اور وہ وہی تھا جو اسلام نے اختیار کیا.مگر عملاً بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہت سے بھی اسلامی
طریق زیادہ کامیاب اور زیادہ مفید نظر آتا ہے کیونکہ اسلامی طریق پر آزاد ہونے والے لوگوں میں ایک
بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے جو ہر قسم کے میدان میں ترقی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے ہیں
اور جنہوں نے مختلف شعبوں میں مسلمانوں میں لیڈر ہونے کا مرتبہ حاصل کیا.مثلاً جیسا کہ اوپر بیان کیا
جاچکا ہے.صحابہ میں زید بن حارثہ ایک آزاد شدہ غلام تھے مگر انہوں نے اتنی قابلیت پیدا کی کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت کی وجہ سے بہت سی اسلامی مہموں میں انہیں امیر العسکر مقرر
ل اصابه واسد الغابہ احوال بلال و ابوسفیان و سهیل بن عمر و
Page 472
۴۵۷
فرمایا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حتی کہ خالد بن ولید جیسے کامیاب جرنیل بھی ان کی ماتحتی میں
رکھے.پھر سالم بن معقل تھے جو ابوحذیفہ بن عقبہ کے معمولی آزاد کردہ غلام تھے مگر وہ اپنے علم وفضل میں
اتنی ترقی کر گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چار صحابیوں کو قرآن شریف کی تعلیم کے لئے
مسلمانوں میں مقررفرمایا تھا اور اس معاملہ میں گویا انہیں اپنا نا ئب بننے کے قابل سمجھا تھا ، ان میں ایک سالم
بھی تھے.اسی طرح صحابہ کے بعد نافع مولی ابن عمر اور عکرمہ مولی ابن عباس اور مکحول بن عبداللہ اور
عطاء بن ابی رباح اور عبداللہ بن مبارک اور محمد بن سیرین حدیث اور فقہ کے امام مانے جاتے تھے جن کی
شاگردی کو بڑے بڑے جلیل القدر لوگ فخر خیال کرتے تھے.پھر حسن بصری تصوف میں اور مجاہد بن جبیر علم
قرآت میں یکتائے زمانہ تھے اور موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق علم تاریخ میں استاذ الکل تھے، جن کے علم کا
لو ہا دنیا مانتی تھی.مگر یہ سب لوگ معمولی غلام سے اس مرتبہ کو پہنچے تھے.لے پھر ہندوستان کا خاندان غلاماں
بھی جس کے بعض ممبروں نے سیاست اور ملک داری میں کمال پیدا کیا کسی معرفی کا محتاج نہیں.یہ درخشندہ
مثالیں جو صرف بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں (ورنہ اسلام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے)
اسلامی طریق آزادی کا ثمرہ ہیں.مگر اس کے مقابلہ میں مغربی مصلحین کی اصلاح کا ثمرہ کیا ہے؟ کیا سارے
یورپ و امریکہ اور سارے افریقہ و آسٹریلیا میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نظر آتی ہے کہ کبھی کسی آزاد شدہ
غلام نے کسی میدان میں ایسی لیڈری اور امامت کا مرتبہ حاصل کیا ہو کہ آزاد کر نے والی قوم بھی اسے
اپنا مقتد التسلیم کرنے لگ جاوے؟ ہمیں اقوام کی تاریخ کے عبور کا دعویٰ نہیں ہے لیکن جہاں تک ہمارا علم
ہے ہمیں مسیحی اقوام کے آزاد کردہ غلاموں میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ ان غلاموں میں سے کبھی
کسی نے کوئی خاص نمایاں امتیاز پیدا کیا ہو بلکہ یہی نظر آتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد بھی یہ لوگ معمولی درجہ
کے انسان رہے ہیں.جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی طریق آزادی یقیناً بہت زیادہ نفع مند اور بہت
زیادہ با برکت تھا.اندریں حالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے مقابلہ میں موجودہ زمانہ کے
کسی مصلح کا نام لینا صداقت کی ہتک کرنا ہے.بیشک ہم ان لوگوں کے کام کو بھی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں
اور ان کی کوششوں کے مداح ہیں.مگر ہر شخص کی کوشش کا ایک مرتبہ ہوتا ہے اور حق یہ ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں کسی شخص کی کوشش کا نام نہیں لیا جاسکتا.آج سے چودہ سو سال قبل جبکہ دنیا غلامی کو اپنا پیدائشی حق سمجھے ہوئے تھی اور غلاموں کی حالت جانوروں سے
تہذیب التہذیب و اکمال وغیرہ
Page 473
۴۵۸
بدتر ہورہی تھی اس وقت آپ کا غلاموں کی حمایت میں آواز اٹھانا اور آئندہ کے لئے غلامی کے ظالمانہ طریقوں
کو قطعی طور پر منسوخ کر کے موجود الوقت غلاموں کی حالت کی اصلاح کے لئے نہایت دانشمندانہ عملی تدابیر
اختیار کرنا اور پھر ان غلاموں کی آزادی کے متعلق پُر زور سفارشات کرنے کے علاوہ ایک ایسا پُر حکمت
انتظام جاری کردینا کہ جس کے نتیجہ میں یہ غلام اپنی حالت کو بھی بہتر بناتے جائیں اور ساتھ ساتھ
لازماً آزاد بھی ہوتے جائیں اور حکومت کا یہ فرض مقرر کرنا کہ وہ غلاموں کی حالت کی اصلاح اوران کی
تدریجی مگر لازمی آزادی کے عمل کی سختی کے ساتھ نگرانی کرے اور پھر اس انتظام کو اس خوبی کے ساتھ چلانا کہ
جو غلام آزاد ہوئے اور ان کی تعداد کروڑوں تھی وہ نہ صرف حقیقی معنوں میں آزاد ہوئے بلکہ وہ ملک وقوم کے
نہایت مفید شہری بھی بن گئے.اور ان میں سے وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانوں میں امارت وامامت
کا مرتبہ حاصل کیا جن کے سامنے ان کے آزاد کرنے والوں کی گردنیں بھی جھک گئیں.یہ وہ کام ہے جو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ وہ کام ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی پس عامی لوگوں کی
طرح یہ اعتراض اٹھانا کہ ابراہام لنکن یا دوسرے مغربی لوگوں کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلاموں
کو یکانت کیوں نہیں آزاد کر دیا جذبات انسانی کا ایک محض سطحی ابال ہے جس کے
اندر کوئی بھی گہرائی نہیں.اسلامی ممالک میں غلامی کیوں قائم رہی؟ اس موقع پر یہ سوال بھی پیدا کیا گیا ہے کہ
اگر اسلام کی تعلیم کا اصل منشا یہ تھا کہ غلام آہستہ
آہستہ آزاد ہو جائیں تو پھر اسلامی ممالک میں موجودہ زمانہ تک غلامی کا سلسلہ کیوں جاری رہا ہے؟ اس کا
جواب یہ ہے کہ جب تک ایک طرف تو اسلامی حکومت ترقی کرتی گئی اور اس کے اثر کا دائرہ وسیع ہوتا گیا
اور دوسری طرف مسلمان اسلامی تعلیمات کی اصل روح کو سمجھتے رہے اور اس پر کار بند ر ہے اس وقت تک
غلاموں کی آزادی کی تحریک نہایت سرعت کے ساتھ جاری رہی اور مسلمانوں کی کوشش سے کروڑوں غلام
داغ غلامی سے نجات پاگئے ، لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اس زمانہ میں دنیا میں غلاموں کی تعداد بے شمار
اور بے حساب تھی اور دنیا کا کوئی متمدن ملک ایسا نہیں تھا جہاں نہایت کثرت کے ساتھ غلام نہ پائے جاتے
ہوں.پس پیشتر اس کے کہ یہ نہ ختم ہونے والا خزانہ ختم ہوتا.ایک طرف تو اسلامی فتوحات کی رو آہستہ
آہستہ کمزور ہو کر بالآخر بالکل رک گئی.اور دوسری طرف زمانہ نبوی کے بعد کے نتیجہ میں وہ نور نبوت کی
روشنی جس سے یہ سارا باغ و بہار تھا مسلمانوں کے دلوں میں مدھم پڑنی شروع ہوگئی اور اسلامی تعلیمات کی
حقیقت کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا وہ ولولہ انگیز شوق جسے صحابہ لے کر اٹھے تھے اور جوصحابہ نے اپنے
Page 474
۴۵۹
پیچھے آنے والوں کو ورثہ میں دیا تھا وہ مسلمانوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گیا بلکہ اس فیج اعوج
کے زمانہ میں وہ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی جہالت یا دنیا داری کے نتیجہ میں دین کو بگاڑ کر اسے کچھ
کا کچھ رنگ دے دیا.جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری قوموں کی طرح جو ابھی تک غلامی کی نہایت مکر وہ صورت
پر کار بند تھیں مسلمان بھی اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایات کو چھوڑ کر غلامی کی اس ظالمانہ صورت کی
طرف لوٹ گئے جس کے استیصال کے لئے اسلام کھڑا ہوا تھا اور گواس کج خیالی اور کجروی کے زمانہ میں
بھی اسلامی ممالک میں غلاموں کی حالت دوسرے ممالک کی نسبت بحیثیت مجموعی اچھی رہی ہے اور مسلمان
لوگ ظاہری طور پر غلام رکھتے ہوئے بھی کبھی غلامی کی اصل روح کے حامی نہیں بنے.اور اس کے مقابلہ
میں ابی سینیا کے عیسائی ملک میں تو اس وقت تک غلامی کی وہ بھیا نک صورت قائم ہے جسے دیکھ کر انسانیت
شرماتی ہے اور یورپ و امریکہ کے مہذب اور متمدن عیسائی ممالک میں بھی ابھی تک غلامی کی روح پر
موت نہیں آئی لیکن کسی ہمسایہ قوم کی خراب تر حالت ہماری خرابی کے داغ کو دھو نہیں سکتی اور اس بات کی
فوری اور اشد ضرورت ہے کہ اسلامی حکومتیں اور اسلامی سوسائٹیاں پوری توجہ اور پوری کوشش کے ساتھ
غلامی کے ظالمانہ طریق کو مٹانے میں لگ جائیں اور دنیا کو پھر اس مبارک نقطہ پر لے آئیں جس پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اسے قائم کرنا چاہتے تھے اور جس کا مقصد دنیا سے غلامی اور اس کی
روح کو مٹانا اور حقیقی آزادی اور حقیقی مساوات کا قائم کرنا تھا.غلاموں کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں اس بحث کو ان
نہایت درجہ پیارے
الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں جو اس مادی دنیا میں مقدس بانی اسلام کے آخری الفاظ تھے.حضرت علی بن
ابی طالب اور انس بن مالک روایت کرتے ہیں:
كَانَ اخِرُ كَلاَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَرُغِرُ بِنَفْسِهِ الصَّلَوةُ وَ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
یعنی آخری الفاظ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے گئے اس حال میں کہ
آپ پر موت کا غرغرہ طاری تھا یہ تھے کہ الصَّلوةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ یعنی اے مسلمانو!
میری آخری وصیت تم کو یہ ہے کہ نماز اور غلاموں کے متعلق میری تعلیم کو نہ بھولنا.“
لی ابن ماجہ ابواب الوصیت نیز نسائی عن انس و مسند احمد عن ام سلم" بحوالہ جامع الصغیر جلد ۲ صفحہ ۴۲
Page 475
۴۶۰
اس وقت جبکہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے.آپ کی وہ رفیق حیات بیویاں جنہوں نے ہر تنگی و ترشی میں
آپ کا ساتھ دیا تھا آپ کے پاس تھیں.آپ کی لخت جگر صاحبزادی اور اس کے بچے اور آپ کے
دوسرے عزیز واقارب بھی سامنے تھے.وفادار مہاجرین کی مخلصانہ رفاقت میں آپ کی عمر گزری تھی وہ بھی
موجود تھے.جان نثار انصار جنہوں نے اپنے خون کے پانی سے اسلام کے پودے کو سینچا تھا وہ بھی قریب
تھے اور یہ وقت بھی وہ تھا جس کے بعد آپ کو کسی اور کو نصیحت کے کرنے کا موقع نہیں ملنا تھا اور آپ اس
بات کو بھی جانتے اور محسوس کرتے تھے کہ ایسے وقت کی نصیحت آپ کی ساری نصیحتوں سے زیادہ وزن
رکھے گی مگر آپ کی نظر ان لوگوں میں سے کسی پر نہیں پڑی اور اگر دنیا میں سے آپ نے کسی کو یاد کیا اور اس
کی یاد نے موت کے غرغرہ میں بھی آپ کو بے چین کر دیا تو وہ یہی مظلوم غلام تھے.اللہ ! اللہ ! ! غلاموں کا
یہ کیسا سچا دوست کیسا دردمند مخلص تھا جو خدا نے دنیا کو عطا کیا مگر افسوس کہ دنیا نے اس کی قدر نہیں کی.آئندہ غلامی کو روکنے کے لئے اب ہم اس بحث کے دوسرے سوال کو لیتے ہیں اور جو
اس امر سے تعلق رکھتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مسئلہ غلامی کے متعلق اصولی طور پر کیا تعلیم دی ہے یعنی
موجود الوقت غلاموں کے سوال سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ نے آئندہ کے لئے غلامی کے مسئلہ اور غلام
بنائے جانے کے متعلق کیا اصولی احکام صادر فرمائے ہیں لیکن چونکہ گزشتہ بحث نے ہمارے اندازہ سے
بہت زیادہ جگہ لے لی ہے اس لئے اگلی بحث کو ہم نہایت مختصر طور پر بیان کریں گے.سواس کے متعلق سب
سے پہلے یہ جاننا چاہئے کہ یہ بحث در اصل دو حصوں پر منقسم ہے.اول حقیقی غلامی کا سوال یعنی کسی آزاد
انسان کو اس کی جائز آزادی کے حق سے کلیتہ اور مستقل طور پر محروم کر دینا.یہ صورت غلام بنانے کے ان
طریقوں سے تعلق رکھتی ہے جو مذہبی جنگوں میں قیدی پکڑے جانے کے علاوہ ہیں.یعنی غلام بنانے کے
بہت سے ظالمانہ طریق جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دنیا کے تمام ممالک میں کم و بیش رائج
تھے اور اسلام کے بعد بھی مختلف غیر اسلامی ممالک میں رائج رہے.دوسرے مذہبی جنگوں میں قیدی
پکڑنے جانے کا سوال جسے اسلامی تعلیم کی روشنی میں گویا ایک قسم کی غیر حقیقی غلامی کہہ سکتے ہیں.لے : ہم نے جو اس جگہ حقیقی اور غیر حقیقی غلامی کے الفاظ استعمال کئے ہیں اس کے متعلق یہ بتادینا ضروری ہے کہ یہ کوئی
اسلامی اصطلاح نہیں ہے بلکہ ہم نے خود اپنی طرف سے اسلامی تعلیم کی روشنی میں بحث کی سہولت کے لئے یہ اصطلاح قائم
کی ہے.وَلِكُلَّ أَنْ يُصْطَلِحَ.
Page 476
۴۶۱
پہلے ہم مقدم الذکر بحث کو لیتے ہیں.سو اس کے متعلق جاننا چاہئے کہ جیسا کہ گزشتہ بحث میں اشارہ
کیا جا چکا ہے.اسلام نے حقیقی غلامی کو یعنی غلامی کے ان ظالمانہ طریقوں کو جو مذہبی جنگوں میں قیدی
پکڑے جانے کے علاوہ ہیں یکدم اور قطعی طور پر منسوخ کر دیا تھا مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس بارے میں کوئی
معین اور منصوص اسلامی احکام پیش کریں ہم اس کے متعلق دو منفی قسم کے دلائل ہدیہ ناظرین کرنا چاہتے ہیں.پہلی دلیل یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ اصولی طور پر اسلام بڑی سختی کے ساتھ ظلم و تعدی کے طریق سے
منع فرماتا ہے اور انسانی آزادی اور انسانی مساوات کا نہایت زبر دست حامی ہے اور یہ تمام باتیں حقیقی
غلاموں کے طریق سے بعد المشرقین رکھتی ہیں وہ واضح اور پر زور تعلیم جو اسلام نے حاضر الوقت غلاموں
کے ساتھ محسنانہ اور مساویانہ سلوک کئے جانے اور ان کی آزادی کے متعلق دی ہے اور جس کا ایک خاکہ اوپر
درج کیا جاچکا ہے وہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ اسلام غلامی کے ظالمانہ طریق کی تائید میں نہیں
ہوسکتا.انسانی عقل ہر گز اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ غلاموں کو اپنا بھائی سمجھو
اور انہیں اپنے گھر کے آدمیوں کی طرح رکھو اور ان کی تعلیم وتربیت کا خاص انتظام کرو اور پھر جوں جوں ان
کی حالت بہتر ہوتی جاوے اور وہ دنیا میں آزاد زندگی گزارنے کے قابل بنتے جائیں انہیں آزاد کرتے
جاؤ.اسلام میں یہ تعلیم بھی دی جاسکتی تھی کہ کسی آزاد انسان کو اس کی جائز آزادی کے حق سے کلیتہ محروم
کر کے حقیقی طور پر غلام بنانا جائز ہے.ان دونوں قسم کی تعلیم میں بعد القطبین ہے اور وہ کبھی بھی کسی ایک
ہی شخص کی تعلیم کا حصہ نہیں بن سکتیں.پس غور کیا جاوے تو دراصل وہ تعلیم ہی جس کا خاکہ اوپر والے مضمون
میں درج کیا گیا ہے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلام میں حقیقی غلامی کی تعلیم نہیں دی گئی.دوسری دلیل جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں حقیقی غلامی کو جائز نہیں سمجھا گیا یہ ہے کہ اسلامی
لٹریچر کے کسی حصہ میں یہ حکم موجود نہیں کہ کسی آزاد شخص کو اس کی آزادی کے جائز حق سے محروم کر کے حقیقی
طور پر غلام بنا لینا جائز ہے یا یہ کہ اگر کسی آزاد شخص کو غلام بنانا ہو تو اس کا یہ یہ طریق ہے.حالانکہ غلامی کے
دوسرے مسائل مثلاً غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے اور انہیں آزاد
کرنے کے متعلق اسلامی شریعت میں نہایت تفصیلی احکام موجود ہیں.پس غلاموں کے بارے
میں دوسرے ہر قسم کے مسائل کا پایا جانا، لیکن غلام بنانے کے سوال کے متعلق قطعاً کسی جوازی حکم کا پایا
نہ جانا اس بات میں ہرگز کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑتا کہ دراصل اسلام میں حقیقی غلامی کو جائز ہی نہیں سمجھا
گیا.میں نے بہت تلاش کی ہے مگر مجھے کسی قرآنی آیت یا کسی روایت میں خدایا اس کے رسول کا یہ حکم نظر
Page 477
۴۶۲
نہیں آیا کہ کسی آزاد انسان کو حقیقی طور پر غلام بنانا جائز ہے یا یہ کہ کسی آزاد شخص کو غلام بنانا ہو تو اس کا یہ
طریق ہے.حالانکہ اگر اسلام میں کسی آزاد انسان کو حقیقی طور پر غلام بنانا جائز ہوتا تو غلامی کے جملہ مسائل
میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ وسیع الاثر اور سب سے زیادہ نازک مسئلہ جو توضیح و تنصیص کا
حقدار تھا اور جس میں ایک نہایت واضح اور منصوص حکم دیئے جانے کی ضرورت تھی وہ یہی غلام بنانے
کا مسئلہ تھا مگر تخصیص و توضیح تو الگ رہی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر تک نہیں ہے جو اس بات کی ایک
یقینی دلیل ہے کہ اسلام میں کسی آزاد شخص کو حقیقی طور پر غلام بنا نا جائز نہیں ہے.لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے.ہمارے دعویٰ کی بنیا د صرف منفی قسم کے دلائل پر نہیں ہے بلکہ
خدا کے فضل سے اسلامی شریعت میں نہایت واضح اور منصوص طور پر یہ حکم موجود ہے کہ کسی آزاد انسان کو
اس کی جائزہ آزادی سے محروم کر کے غلام بنانا ایک سخت ممنوع اور حرام فعل ہے جس کے متعلق قیامت کے
دن خدا کے حضور سخت مواخذہ ہوگا.چنانچہ حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعٍ حُرًّا فَا كِلْ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اَجِيْرًا
فَاسْتَوْفِى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ
یعنی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جنگ
کروں گا.اول وہ شخص جو میر ا واسطہ دے کر کسی سے کوئی عہد باندھتا ہے اور پھر غداری کرتا ہے.دوسرے وہ جو کسی آزاد شخص کو غلام بناتا ہے اور اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کھا جاتا ہے اور
تیسرے وہ جو کسی شخص کو کام پر لگاتا ہے اور پھر اس سے کام تو پورا لے لیتا ہے مگر اس کی مزدوری
اسے نہیں دیتا.“
اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ لا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرًا....الخ
یعنی ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے
مجھے فرمایا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کی نماز میرے حضور ہرگز قبول نہیں ہوگی اور میں ان سے
بخاری کتاب البيع
ابو داؤد بروایت فتح الباری جلد ۴ صفحه ۳۴۶
Page 478
۴۶۳
قیامت کے دن لڑوں گا.ایک وہ شخص جو میرا واسطہ دے کر کسی سے کوئی عہد باندھتا ہے اور پھر
بد عہدی کرتا ہے.دوسرے وہ جو اسے غلام بنا تا ہے جسے خدا نے آزاد رکھا ہے اور تیسرے وہ جو
مزدور سے کام لیتا ہے اور پھر اس کی مزدوری نہیں دیتا.“
ان حدیثوں میں جس وضاحت اور تعیین کے ساتھ اور جس زور دار طریق پر حقیقی غلامی کو منسوخ کیا گیا
ہے وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں ہے اور پھر یہ حدیثیں بھی حدیث کی اس قسم میں داخل ہیں جو محدثین کی
اصطلاح میں حدیث قدسی کہلاتی ہے یعنی جو ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے مگر
اس میں حکم اور الفاظ خدا کے ہوتے ہیں.اب اس واضح اور صریح تعلیم کے ہوتے ہوئے کسی کا یہ کہنا کہ
اسلام میں حقیقی غلامی کو جائز رکھا گیا ہے یعنی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی آزاد انسان کو اس کی
جائز آزادی کے حق سے محروم کر کے حقیقی طور پر غلام بنالیا جاوے ایک انتہائی درجہ کا ظلم ہے جس کے
ارتکاب کی کوئی دیانت دار شخص جرات نہیں کر سکتا.جنگی قیدیوں کا مسئلہ اب ہم جنگی قیدیوں کے سوال کو لیتے ہیں اور در حقیقت اگر اسلام میں غلام
بنانے کے جواز کی کوئی صورت سمجھی جاسکتی ہے تو وہ صرف اسی سوال کے
ماتحت آتی ہے، لیکن جیسا کہ ابھی ظاہر ہو جائے گا غلامی کی یہ قسم دراصل حقیقی غلامی نہیں ہے بلکہ ایک محض
جزوی مشابہت کی وجہ سے اسے یہ نام دے دیا گیا ہے اور پھر اس غیر حقیقی غلامی کو بھی اسلام نے ایسی شرائط
کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ وہ ایک عالمگیر چیز نہیں رہتی بلکہ بعض خاص قسم کے حالات میں محدود ہو جاتی
ہے اس بحث میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہئے کہ جیسا کہ تاریخ عالم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے غلامی کی
ابتدائے دنیا میں جنگی قیدیوں سے ہوئی تھی اور بعد میں آہستہ آہستہ دوسرے ظالمانہ طریق ایجاد ہوتے
گئے.جس کی وجہ سے بالآخر غلامی جو دراصل ابتدائی زمانہ کے حالات کا ایک لازمی نتیجہ تھی ایک بھیانک
صورت اختیار کرگئی اور بجائے ظلم کو روکنے کا باعث بننے کے جو اس کی اصل غرض تھی وہ خود ظلم و ستم کا ایک
خطرناک آلہ بن گئی.ابتداء یہ طریق تھا گو بعد میں اس کے ساتھ اور اور ظالمانہ طریق شامل ہو گئے
( جنہیں نہ صرف اسلام نے مٹادیا بلکہ اس ابتدائی طریق کو بھی مزید پاک وصاف کر کے اسے ایک نہایت
پاکیزہ صورت دے دی ) کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر حملہ آور ہو کر اسے صفحہ دنیا سے مٹا دینے یا اس کی
آزادی کو چھین کر اسے بلا وجہ اپنے ماتحت کر لینے کے درپے ہوتی تھی تو مؤخر الذکر قوم غلبہ حاصل کرنے پر
حملہ آور قوم کے آدمیوں کو قید کر کے اپنے پاس روک لیتی تھی کیونکہ اگر ظالم لوگوں کو اس طرح روک لینے کا
Page 479
۴۶۴
طریق اختیار نہ کیا جاتا تو بین الاقوام جنگوں کا کبھی بھی خاتمہ نہ ہوسکتا اور ظالم لوگ اپنی دراز دستیوں
اور امن شکن کارروائیوں سے باز نہ آتے اور ظلم و ستم کا میدان وسیع ہوتا چلا جاتا.چنانچہ تاریخ سے پتہ لگتا
ہے کہ اس قسم کی غلامی کا طریق ابتدائی زمانہ میں تمام اقوام عالم میں کم و بیش پایا جاتا تھا.حتی کہ بنو اسرائیل
میں بھی جو نبیوں کی اولاد تھے اور کثیر التعداد نبیوں کے تربیت یافتہ تھے یہ طریق کثرت کے ساتھ رائج تھا
بلکہ اسرائیلی شریعت نے خود اس کا حکم دیا تھا.اور اگر غور کیا جاوے تو اس ابتدائی زمانہ میں مذہبی جماعتوں
کے لئے اس کی ضرورت دوسری قوموں کی نسبت بھی زیادہ تھی.کیونکہ جیسا کہ قاعدہ ہے مذہبی سلسلوں کی
سخت مخالفت ہوتی تھی اور دوسری قومیں انہیں تلوار کے زور سے مٹانے کے لئے کھڑی ہو جاتی تھیں.پس
انہیں بھی دفاع اور خود حفاظتی میں غلامی وغیرہ کے طریق اختیار کرنے پڑتے تھے.اسی طرح مسیحی قوم میں
بھی جو دراصل بنواسرائیل ہی کی ایک شاخ تھے غلامی کا سلسلہ جاری رہا ہے بلکہ اب تک بھی حبشہ کے عیسائی
ملک میں جو اس وقت تک ابتدائی مسیحی روایات پر بڑی سختی کے ساتھ قائم ہے غلامی کا رواج پایا جاتا ہے بلکہ
شاید اس ملک کی غلامی دوسرے ممالک کی غلامی سے بھی سخت تر ہے.اسی طرح ہندوستان کی قدیم آریہ
قوم میں بھی غلامی کا رواج تھا.چنانچہ یہ شودر وغیرہ جو آج تک ہندوستان میں پائے جاتے ہیں یہ اسی
سلسلہ غلامی کا ایک ناگوار بقیہ ہیں.الغرض ابتدائی زمانوں میں غلامی کا رواج کم و بیش سب ممالک اور
سب اقوام میں پایا جاتا تھا اور یہ ان زمانوں کے حالات کا لازمی نتیجہ تھا.اور اس کی غرض ظلم وستم کا
سد باب تھی اور پھر یہ کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت بلکہ حقیقی ضرورت صرف مذہبی جماعتوں کو تھی جو
سب سے زیادہ مظالم کا تختہ مشق بنتی تھیں اور لوگ ان کے مذہب کو تباہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے
تھے اور اس رنگ کی غلامی جسے اسلام نے اور بھی پاک وصاف کر دیا حتی کہ وہ حقیقتاً ایک محض قید کی صورت
اختیار کر گئی کوئی نا انصافی نہیں تھی کیونکہ جو قوم دوسروں کے مذہب کو تلوار کے زور سے مٹانا چاہتی ہے اور
ظالم و سفاک ہے اور امن شکنی کا طریق اختیار کر کے ملک میں
فتنہ وفساد اور قتل وغارت کا بیج ہوتی ہے وہ
ہرگز آزادی کی حق دار نہیں سمجھی جاسکتی جیسے کہ ایک چور یا ٹھگ یا ڈا کو جیل خانہ سے باہر رہنے کا حقدار نہیں
سمجھا جاتا اور یہ مظالم سب سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پیش آئے.ہمارے
استثناء باب ۲۰ آیت ۱۴۱۳
افسیوں باب ۶ آیت ۵ و پطرس باب ۲ آیت ۱۸ موجودہ ایڈیشنوں میں اس جگہ غلام کی جگہ نوکر کا لفظ ہے مگر جیسا کہ
سیاق وسباق سے ظاہر ہوتا ہے اصل مفہوم غلام ہی کا ہے.
Page 480
۴۶۵
ناظرین بھولے نہیں ہوں گے کہ کفار نے مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے نہایت درد ناک عذاب دیئے.لے
ان کے دین و مذہب کو بزور مٹانے کے لئے مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالی.اور ان کے محبوب آقا کے
مقدس خون سے اپنے ناپاک ہاتھوں کو رنگنا چاہاتے اور کمزور مگر بے گناہ اور آزاد مسلمانوں کو غلاموں کی
طرح اپنے پاس قید رکھا.اور بے گناہ مسلمانوں کو ذلیل ترین دھو کے کے ساتھ قید کر کے اپنا غلام بنایا
اور پھر ان میں سے بعض کو نہایت ظالمانہ طریق پر تہ تیغ کیا.اور ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنانے کے
لئے سازشیں کیں اور لڑائیاں لڑیں.اور ان کے معزز شہیدوں کا مثلہ کیا اور ان کے ناک کان کاٹ
کر اپنے گلوں میں ہار پہنے ہے اور ان کی معزز مستورات پر وحشیانہ حملے کر کے ان کے حمل گرائے.اور ان کی عصمت شعار بیبیوں کی شرمگاہوں میں نیزے مار مار کر انہیں ہلاک کیا.ان حالات میں اگر ان
ظالموں کو ان کی آزادی سے محروم کر کے مستقل طور پر غلام بنالیا جاتا تو یہ ہرگز نا انصافی نہیں تھی.مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراسر احسان تھا کہ آپ نے ایسے لوگوں میں سے بھی اکثر کو معاف فرما دیا
اور ان میں سے جو لوگ جنگ میں پکڑے جا کر قیدی بنے ان کی آزادی میں بھی سوائے وقتی حد بندی کے
کوئی روک نہیں ڈالی اور اس وقتی حد بندی کے زمانہ میں بھی آپ نے قیدیوں کے آرام و آسائش کے متعلق
ایسے تاکیدی احکام صادر فرمائے کہ ان سے متاثر ہو کر صحابہ نے اپنی قمیصیں اتارا تار کر قیدیوں کو ہاں
اپنے خون کے پیاسے قیدیوں کو دے دیں.نا خود خشک کھجوروں پر گزارہ کیا.اور انہیں پکا ہوا کھانا دیا.آپ پیدل چلے اور انہیں سوار کیا یے کیا دنیا کی کسی قوم میں کسی زمانہ میں اس کی مثال ملتی ہے؟
جنگی قیدیوں کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ تین قرآنی آیتوں میں آجاتا ہے جن میں سے دو تو خاص
جنگی قیدیوں کے متعلق ہیں اور ایک اصولی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
ما كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ
: زرقانی جلد اصفحه ۲۶۶ تا ۲۷۰
: سورۃ انفال : اے
:
: سورۃ انفال : ۳۱
: سورة بقره : ۲۲۲
بخاری و کتب تاریخ حالات واقعہ رجمیع و بئر معونه
ابوداؤ د باب في خبر النضیر وزرقانی حالات غزوہ ذی قرد ك : کتب احادیث و تاریخ حالات غزوہ احد
ابن ہشام حالات قیدیان بد رو ذکر ا بولعاص بن الربیع
اسدالغابہ حالات سمیه وزرقانی جلد اصفحه ۲۶۶
ال ابن ہشام حالات قیدیان بدر
بخاری کتاب الجہاد باب الكسوة الأسارى
میور حالات قیدیان غزوہ بدر
Page 481
۴۶۶
عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُه :
یعنی نبی کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ اس کے لئے جنگی قیدی پکڑے جائیں حتی کہ دشمن
کے ساتھ کسی میدان میں اچھی طرح عملی جنگ نہ ہوئے.اے مسلمانو! تم قریب کے فوائد پر نگاہ
رکھتے ہو ( کہ قیدی پکڑنے میں جلدی کی جاوے تاکہ تم ان کے فدیہ کی رقم سے دشمن کے مقابلہ کی
تیاری کر سکو ) مگر اللہ تعالیٰ انجام کار کو دیکھتا ہے ( اور چونکہ انجام کے لحاظ سے یہ طریق پسندیدہ
نہیں اور اخلاقی طور پر اس کا اثر خراب ہے اس لئے وہ تمہیں اس طریق سے باز رہنے کا حکم دیتا ہے )
اور اگر تمہیں دشمن کی تعداد و طاقت کا خوف ہو تو جانو کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں پر غالب ہے اور
وہ حکیم یعنی تمہاری حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے.“
اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کمزوری اور دشمن کی طاقت کے خیال سے
یا فدیہ کے ذریعہ اپنی مالی حالت کو مضبوط بنانے کی غرض سے دشمن کے قیدی پکڑنے کے معاملہ میں جلدی
اور بے احتیاطی سے کام نہیں لینا چاہئے کہ جہاں بھی دشمن کو کمزور پایا قیدی پکڑنے شروع کر دیئے یا میدان
جنگ میں عملی مقابلہ ہونے سے پہلے ہی قیدی پکڑ لئے بلکہ مسلمانوں کو صرف اس صورت میں قیدی پکڑنے
کی اجازت ہے کہ میدان جنگ میں عملاً دشمن کا مقابلہ ہو اور لڑائی کے بعد قیدی پکڑے جائیں.اس
اسلامی تعلیم میں جو بین الاقوامی ضابطہ جنگ کی اعلی ترین بنیاد پر قائم ہے جنگی قیدیوں کی تعداد اور وسعت
کو امکانی طور پر تنگ سے تنگ دائرہ میں محدود کر دیا گیا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کا منشا یہ
تھا کہ سوائے ان صورتوں کے جو لا بدی اور اٹل ہوں حتی الوسع جنگی قیدی نہیں پکڑنے چاہئیں.پھر فرماتا ہے:
فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا اثْخَنْتُمُوهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا :
یعنی ”اے مسلمانو! جب کفار کے ساتھ تمہاری جنگ ہو تو خوب جم کر لڑو اور ظالموں کو قتل کرو
اور جب اچھی طرح جنگ ہولے تو اس کے بعد دشمن کے آدمیوں میں سے قیدی پکڑو.پھر اگر
اصلاح کی امید ہو اور حالات مناسب ہوں تو ان قیدیوں کو بعد میں یونہی احسان کے طور پر چھوڑ
دو یا مناسب فدیہ لے کر انہیں رہا کر دو اور یا اگر ضروری ہو تو انہیں قید میں ہی رکھو حتی کہ جنگ ختم
: سورۃ انفال : ۶۸
: سورة محمد : ۵
Page 482
۴۶۷
ہو جاوے اور اس کے بوجھ تمہارے سروں سے اتر جاویں.“
یہ آیت جنگی قیدیوں کے متعلق اسلامی شریعت میں بطور بنیادی پتھر کے ہے جس میں وہ مختلف صورتیں
بنادی گئی ہیں جو قیدیوں کے معاملہ میں مختلف حالات کے ماتحت اختیار کی جاسکتی ہیں.اور وہ تین ہیں:
اوّل : بطور احسان چھوڑ دینا.دوم: فدیہ لے کر چھوڑ دینا.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل
سے پتہ لگتا ہے کہ فدیہ کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں (0) نقد فدیہ خواہ وہ یکمشت اور فوری ادائیگی کی صورت
میں ہو یا مکا تبت کے اصول پر جس کی مفصل بحث او پر گزر چکی ہے ( ب ) مسلمان قیدیوں کے ساتھ تبادلہ
(ج) کوئی مناسب خدمت لے لینا مثلاً اگر قیدیوں کو کوئی فن آتا ہو تو ان کے ساتھ یہ شرط کر لینا کہ اگر وہ
بعض مسلمانوں کو یہ فن سکھا دیں تو رہا کر دیئے جائیں گے.سوم : قید کی حالت کو ہی جنگ کے اختتام تک لمبا کر دینا اور جنگ کے اختتام سے اس کا کامل اختتام
مراد ہے جبکہ وہ صرف جنگی کارروائیوں کا سلسلہ عملاً ختم ہو جاوے بلکہ وہ بوجھ بھی جو اس کی وجہ سے ملک
اور قوم پر پڑے ہوں اور جن کی ذمہ داری دشمن قوم پر سمجھی جاوے دور ہو جائیں.جیسا کہ قرآنی الفاظ
حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزارھا میں اشارہ پایا جاتا ہے.اور یہ آخری صورت اس لئے تجویز کی گئی ہے
کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ نہ تو کفار کے قیدیوں کو احسان کے طور پر چھوڑ نا قرین مصلحت ہواور نہ ہی وہ
یا ان کے رشتہ دارا اپنی ضد یا عداوت کی وجہ سے فدیہ ادا کرنے پر آمادہ ہوں تو پھر انہیں جنگ کے حقیقی
اختتام تک قید رکھا جا سکے تاکہ ان کے رہا ہونے سے مسلمانوں کی مشکلات اور خطرات میں اضافہ نہ ہو اور
یہی وہ صورت ہے جسے اسلام میں غلامی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور جس کی اسلام نے اجازت دی ہے
مگر غور کیا جاوے تو دراصل یہ غلامی نہیں بلکہ محض ایک قید ہے اور پھر اس قید یا غیر حقیقی غلامی کو بھی اسلام
نے ایک اصولی قاعدہ کے ساتھ مشروط ومحدود کر دیا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
ط
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِع وَلَبِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصُّبِرِينَ
یعنی ”اے مسلمانو! اگر تم کفار کے مقابلہ میں انتقام اور سزا کے طریق پر کوئی سختی کرنا مناسب
خیال کرو تو ضروری ہے کہ تمہاری سختی اس سختی سے تجاوز نہ کرے جو کفار تمہارے خلاف کرتے ہوں
اور یہ بھی ضروری ہے کہ تم کوئی ایسی سختی نہ کرو جس میں کفار نے سبقت اور پہل نہ کی ہوا اور اگر
تمہارے لئے صبر کرنا ممکن ہو تو پھر صبر ہی سے کام لو کیونکہ صبر کرنا بہتر ہے.“
: سورة نحل
۱۲۷ :
Page 483
۴۶۸
اس اصولی آیت کے ماتحت جنگی قیدیوں کے متعلق وہ صورت جو قید کی حالت کے لمباکئے جانے سے
تعلق رکھتی ہے مختلف رنگ اختیار کر سکتی ہے.مثلاً اگر کفار مسلمان قیدیوں سے خدمت لیتے ہوں تو مسلمان
بھی کفار کے قیدیوں سے مناسب خدمت لے سکتے ہیں.مگر یہ خدمت بہر حال ان شرائط کے ماتحت ہوگی
جو غلاموں وغیرہ سے خدمت لینے کے متعلق اسلام نے مقرر فرمائی ہیں.مثلاً یہ کہ ان کو ان کی طاقت سے
زیادہ کام نہ دیا جاوے اور ایسا کام نہ دیا جاوے جسے آقا خود کرنے کے لئے تیار نہ ہو.اسی طرح اگر کفار
مسلمان قیدیوں کو بجائے قومی اور ملکی قید خانوں میں رکھنے کے اپنے افراد میں تقسیم کر دیتے ہوں تو مسلمان
بھی کفار کے قیدیوں کو مسلمان افراد کی سپردگی میں دے سکتے ہیں.وغیر ذالک.مگر بہر حال یہ ضروری ہے
کہ اس قسم کی تفصیلات میں جو صورت بھی اختیار کی جاوے وہ کسی مخصوص اسلامی حکم کے خلاف نہ ہو.مثلاً یہ
کہ یہ ضروری ہے کہ قید کا سلسلہ جنگ کے اختتام پر لازما ختم کر دیا جاوے یا یہ کہ قیدی محض دشمن کی فوج
کاسپاہی ہونے کی وجہ سے قتل نہ کیا جاوے یا یہ کہ قیدیوں سے خدمت ان کی طاقت اور حیثیت کے
مطابق لی جاوے تے یا یہ کہ قیدیوں کے آرام و آسائش کا خاص خیال رکھا جائے.وغیر ذالک
یہ وہ تعلیم ہے جو جنگی قیدیوں کے متعلق اسلام دیتا ہے.اب ناظرین خود انصاف کے ساتھ غور کریں
کہ خواہ نام کے لحاظ سے اسے غلامی کہہ دیا جائے مگر کیا اس تعلیم میں کوئی حقیقت غلامی کی پائی جاتی
ہے؟ کیا آج کل کی حکومتیں جنگی قیدی نہیں پکڑتیں؟ کیا آج کل کی حکومتیں جنگی قیدیوں سے خدمت نہیں
لیتیں ؟ پھر کیا آج کل کی حکومتیں جنگی قیدیوں کی قید کے عرصہ کو جنگ کے لمبا ہو جانے کی صورت میں لمبا
نہیں کر دیتیں؟ جب یہ سب کچھ ہر قوم میں ہوتا ہے اور اب بھی ہوتا ہے اور ہر زمانہ میں بین الاقوامی قانون
اسے جائز قرار دیتا ہے تو پھر از روئے انصاف اس بنا پر اسلام اور بانی اسلام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا
بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا ایک احسان ہے کہ اس نے جنگی ضابطہ میں نرمی اور شفقت کے عصر کونمایاں
کر کے دنیا کے امن اور اتحاد بین الاقوام کے لئے راستہ صاف کر دیا ہے.باقی رہا انفرادی قبضہ کا سوال
سو یہ درست ہے کہ ابتدا میں کفار کے قیدی عام طور پر مسلمان سپاہیوں میں تقسیم کر دیئے جاتے تھے
اور دراصل یہی ایک بات ہے جو اس قانون کو غلامی کا رنگ دینے والی سمجھی جاسکتی ہے مگر غور کیا جاوے
تو یہ بات ان حالات میں جن کے ماتحت اسے اختیار کیا جاتا رہا ہے ہرگز قابل اعتراض نہیں ہے اور نہ
: سورة محمد : ۵ وکتاب الخراج صفحه ۱۲۱
: سورة محمد : ۵
بخاری کتاب العتق
: سورة الدهر : ۱۰۹ و بخاری کتاب الجهاد و طبری و غیره
Page 484
۴۶۹
اسے حقیقی غلامی سے یعنی غلامی کی اس اصطلاح سے جو غیر اسلامی دنیا میں رائج ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے کیونکہ
اول تو یہ طریق اسلام میں بالذات اختیار نہیں کیا گیا اور نہ مخصوص تعلیم میں جو اسلام جنگی قیدیوں کے متعلق
دیتا ہے اس کا کوئی ذکر پایا جاتا ہے.بلکہ در حقیقت یہ ایک جوابی تد بیر تھی جو کفار کے ظالمانہ رویہ کی وجہ
سے اختیار کی گئی تھی یعنی چونکہ کفار مسلمان قیدیوں کو غلام بنا کر اپنے افراد میں تقسیم کر دیتے تھے اس لئے
انہیں ہوش میں لانے کی غرض سے اسلام میں بھی کفار کے قیدیوں کو مسلمانوں کی انفرادی حراست
میں دے دینے کا طریق اختیار کیا گیا.مگر پھر بھی اسلام نے ان قیدیوں کو اس رنگ میں غلام بنانے کی
اجازت نہیں دی جیسا کہ کفار بناتے تھے نیز یہ شرط کہ جنگ کے اختتام پر وہ لازماً آزاد کر دیئے جائیں.دوسری وجہ انفرادی حراست کے طریق اختیار کئے جانے کی یہ تھی کہ اس زمانہ میں شاہی قید خانوں کا دستور
نہیں تھا بلکہ دشمن کے قیدی فاتح قوم کے افراد میں تقسیم کر دیئے جاتے جو انہیں اپنی زیر نگرانی رکھتے تھے اور
یہی طریق ابتدا میں اسلام میں رائج رہا.پس در حقیقت یہ غلامی نہیں تھی بلکہ قیدیوں کے رکھنے کا ایک سٹم
تھا جو بعد میں آہستہ آہستہ بدل گیا اور اس کی جگہ شاہی قید خانوں کا طریق قائم ہو گیا.یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جہاں تک اسلامی حکومت کا تعلق تھا یہ طریق قیدیوں کے لئے ہر گز تکلیف دہ
نہیں تھا بلکہ یقیناً اس میں ان کو آج کل کے شاہی قیدیوں کی نسبت بھی زیادہ آرام ملتا تھا کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پُر زور تعلیم اور حکومت کی چوکس نگرانی کی وجہ سے کفار کے قیدی مسلمانوں کے جس
خاندان میں رہتے تھے اس کے نوکر اور خادم بن کر نہیں رہتے تھے بلکہ خاندان کے ممبر سمجھے جاتے تھے
اور ان کی خاطر و تواضع مہمانوں کی طرح ہوتی تھی.چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کو جو
عموماً اسلام کے بدترین دشمن تھے مسلمانوں نے اس آرام و آسائش کے ساتھ رکھا کہ وہ ان کی تعریف میں
رطب اللسان تھے اور ان میں سے کئی محض اس حسن سلوک سے متاثر ہوکر مسلمان ہو گئے.الغرض اس
نام نہا د غلامی میں بھی جس کی اسلام اجازت دیتا ہے اسلام نے احسان و مروت کا وہ اعلیٰ نمونہ قائم کیا جو
آج کل کی آزادی کی برکات کو بھی شرماتا ہے لیکن بہر حال چونکہ یہ طریق ایک محض جوابی رنگ رکھتا تھا اس لئے
وہ ان خاص حالات کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے گا جن کے جواب میں وہ اختیار کیا گیا.اور اسی لئے اب
اس زمانہ میں یہی فتویٰ ہے کہ چونکہ آج کل شاہی قیدیوں کا دستور قائم ہوگیا ہے اور مسلمان قیدیوں کو
کفار غلام نہیں بناتے اس لئے شریعت اسلامی کے اصولی حکم کے ماتحت اب مسلمانوں کے لئے بھی یہ جائز
دیکھو آیات سورۃ انفال وسورة محمدمحولہ بالا
میور حالات قیدیان بدر
Page 485
۴۷۰
نہیں ہے کہ وہ کفار کے قیدیوں کو مسلمان افراد میں تقسیم کر کے ایک رنگ غلامی کا پیدا کریں.چنانچہ مقدس
بانی سلسلہ احمدیہ جن کا دعوی خدا کی طرف سے اس زمانہ کے لئے مامور ومصلح ہونے کا تھا تحریر فرماتے ہیں:
یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے زمانہ میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کہلاتے ہیں
انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا ہے اس لئے اب مسلمانوں کے لئے بھی روانہیں
کہ ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام بناویں کیونکہ خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے جو تم جنگجو فرقہ کے
مقابل پر صرف اُسی قدر زیادتی کرو جس میں پہلے انہوں نے سبقت کی ہو.پس جبکہ اب وہ زمانہ
نہیں ہے اور اب کا فرلوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے
کہ ان کو اور ان کے مردوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بناویں بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے
ہیں اس لئے اب اس زمانہ میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا نا جائز اور حرام ہے.“ !
خلاصہ کلام یہ کہ جنگی قیدیوں کے متعلق اسلامی تعلیم کے اصل الاصول صرف دو ہیں.یعنی اول یہ کہ
حتی الوسع قیدی پکڑنے میں جلدی نہ کی جاوے اور صرف انتہائی حالات میں عملی جنگ ہونے کے بعد قیدی
پکڑے جائیں.دوم یہ کہ قیدی پکڑنے کے بعد حالات کے ماتحت یا تو انہیں بلافد یہ احسان کے طور پر
چھوڑ دیا جاوے اور یہ سب سے زیادہ پسندیدہ صورت ہے اور یا مناسب فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا
جاوے اور یا اگر ضروری ہو تو اختتام جنگ تک ان کی قید کے سلسلہ کولمبا کر دیا جاوے.اس سے زیادہ جنگی
قیدیوں کے متعلق کوئی منصوص تعلیم اسلامی شریعت میں پائی نہیں جاتی.البتہ ایک عام قاعدہ کے طور پر
اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ اگر سیاسی اغراض کے ماتحت کفار کے متعلق کوئی سخت جوابی تدبیر اختیار کی جانی
ضروری ہو تو وہ اس شرط کے ماتحت کی جاسکتی ہے کہ اول اس میں کوئی ایسی سختی نہ کی جاوے جس میں کفار
نے خود پہل نہ کی ہو اور دوسرے وہ اسلام کی کسی دوسری منصوص تعلیم کے خلاف نہ ہو.کفار کے قیدیوں کا
مسلمان افراد میں تقسیم کر دیا جانا اسی عام قاعدہ کے ماتحت تھا لیکن چونکہ آج کل کفار مسلمانوں کے قیدیوں
کو غلام نہیں بناتے اور شاہی قیدیوں کے طور پر رکھتے ہیں.اس لئے اس زمانہ میں مسلمانوں کے لئے بھی
ناجائز ہے کہ وہ کفار کے قیدیوں کو مسلمان افراد میں تقسیم کر کے کوئی رنگ غلامی کا پیدا کریں.کیا قیدیوں
کو قتل کیا جاسکتا ہے؟ یہ سوال
کہ آیا قید یوں کوقتل کرنا جائز ہے یانہیں؟ اس کا مجمل
جواب اوپر گزر چکا ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن
چشمه معرفت صفحه ۲۴۴، ۲۴۵ حاشیه
Page 486
چونکہ اس معاملہ میں بعض مسلمان علماء نے بھی اختلاف کیا ہے اور مسیحی مؤرخین نے بھی اسے اعتراض کا
نشانہ بنایا ہے اس لئے اس کے متعلق کسی قدر تشریح کے ساتھ لکھنا ضروری ہے.سوسب سے پہلے تو جاننا
چاہئے کہ سورۃ محمد کی آیت سے جس کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے نہایت واضح طور پر پتہ لگتا ہے کہ جنگی قید یوں
کا قتل کرنا جائز نہیں ہے اور قرآنی فیصلہ کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی اور طریق تجویز کرے
لیکن ناظرین کی مزید تسلی کے لئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآنی آیت کے جو معنے ہم نے کئے ہیں
اس زمانہ کی اختراع نہیں ہے بلکہ یہی معنے صحابہ بھی کرتے تھے اور اسی پر ان کا عمل تھا.چنانچہ حدیث
میں روایت آتی ہے کہ:
عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ الْحَجَّاجَ أُتِيَ بِأَسِيرٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَقُمْ فَاقْتُلُهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَا بِهَذَا
أمِرُنَا يَقُولُ اللهُ تَعَالَى حَتَّى إِذَا الْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُوَ إِمَّا فِدَاءً
یعنی حسن روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حجاج کے سامنے ایک قیدی پیش ہوا اس وقت
حضرت عبد اللہ بن عمرؓ بھی پاس تھے.حجاج نے ابن عمرؓ سے کہا ” آپ اٹھیں اور اس قیدی کی گردن
اڑا دیں.ابن عمرؓ نے جواب دیا.ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا.اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جب
جنگ میں قیدی پکڑے جائیں تو ان کو یا تو احسان کے طور پر چھوڑ دینا چاہئے یا فدیہ لے کر رہا کر
دینا چاہئے قتل کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے.“
اسی طرح حسن بصری اور عطاء بن ابی رباح سے روایت آتی ہے کہ :
لا تُقتَلُ الأسرى يُتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ
یعنی قیدی قتل نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے لئے یہی حکم ہے کہ یا تو اسے احسان کے طور پر
چھوڑ دیا جاوے اور یا فدیہ لے کر رہا کر دیا جاوے.“
قرآن شریف کی محولہ بالا واضح آیت کے ساتھ یہ واضح تشریح مل کر اس بات میں کسی شک وشبہ کی
گنجائش نہیں چھوڑتی کہ قیدیوں کے قتل کے جواز کا مسئلہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے اور اسلام ہرگز اس
بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی جنگی قیدی کو قتل کیا جاوے اور اگر اس جگہ یہ سوال ہو کہ پھر اس معاملہ میں
بعض مسلمان
علماء کو غلطی کیوں لگی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط فہمی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ
تاریخ میں بظاہر ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگی قیدیوں کے قتل کا حکم دیا
کتاب الخراج قاضی ابو یوسف صفحه ۱۲۱
: فتح الباری جلد ۶ صفحه ۱۰۶
Page 487
۴۷۲
تھا وہ جنگی قیدی ہونے کی حیثیت میں قتل نہیں کئے گئے بلکہ ان کے قتل کی وجہ یہ تھی کہ وہ بعض دوسرے جرائم
کی وجہ سے واجب القتل تھے اور یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی قیدی کسی ایسے جرم کا مرتکب ہوا جس کی سز اقتل ہے
تو اس کا قیدی ہونا اسے اس سزا سے نہیں بچا سکتا.اگر ایک آزاد شخص کسی جرم کی سزا میں قتل کیا جاسکتا ہے تو
ایک قیدی کیوں نہیں کیا جاسکتا.پس جیسا کہ اپنے اپنے موقع پر ثابت کیا جائے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے حکم سے جو جو قیدی بھی قتل کیا گیا وہ اس جرم کی بناء پر قتل نہیں کیا گیا کہ وہ ایک دشمن فوج کا سپاہی یا ایک
جنگجو قوم کا فرد ہے بلکہ وہ اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ کسی ایسے جرم کا مرتکب ہو چکا تھا جس کی سزا قتل تھی
لیکن بعض علماء نے صرف ظاہری حالت کو دیکھ کر کہ بعض قیدی قتل کر دیئے گئے تھے یہ نتیجہ نکال لیا کہ قیدی کو
قتل بھی کیا جاسکتا ہے حالانکہ یہ بات اسلامی تعلیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل ہر دو کے لحاظ
سے قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے.یہ اس تعلیم کا ڈھانچہ ہے جو اسلام نے جنگی قیدیوں کے متعلق دی ہے اور ہر عقل مند شخص سمجھ سکتا ہے
کہ یہ ایک نہایت منصفانہ قانون ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خدا نے دنیا کو عطا کیا ہے اور
موجودہ زمانہ کی ترقی یافتہ اور مہذب کہلانے والی اقوام بھی اس سے بہتر قانون دنیا کو نہیں دے سکیں کہ جس
میں اگر ایک طرف جنگ کے ناواجب طور پر طول پکڑ جانے اور بین الاقوامی مظالم کا سد باب کیا گیا ہے تو
دوسری طرف احسان و مروت کے پہلو کو بھی بہترین صورت میں قائم رکھا گیا ہے.بلکہ اگر غور کیا جاوے تو
اس قانون میں دشمن کے ساتھ نرمی اور احسان کا پہلو اپنی حفاظت کے پہلو سے بھی غالب ہے اور یقیناً آج
تک کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس نے اپنے خونی دشمن کے ساتھ جو اسے ملیا میٹ کر دینے کے درپے ہو
ایسے منصفانہ اور محسنانہ سلوک کا حکم دیا ہو.لونڈیوں کا مخصوص مسئلہ اب ہم ایک لفظ لونڈیوں یعنی غلام عورتوں کے متعلق کہہ کر غلامی کی بحث
کو ختم کرتے ہیں.یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے لونڈیوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی عام اجازت دے کر نعوذ باللہ اپنے متبعین کے لئے تعیش کا دروازہ
کھول دیا ہے.اس کے متعلق ہم سب سے پہلے اصولی طور پر یہ بتادینا چاہتے ہیں کہ اسلام میں مرد و عورت
کے مخصوص تعلق کی غرض وغایت کیا رکھی گئی ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اعمال
کو حج کرنے اور ان کے پیچھے جو نتیں مخفی تھیں ان کا پتہ لگانے کے لئے سب سے زیادہ صحیح ذریعہ یہ ہے کہ یہ
دیکھا جاوے کہ جس مذہب کے احکام کی تعمیل میں آپ اور آپ کے صحابہ یہ اعمال بجالاتے اور ان کی
Page 488
۴۷۳
اجازت دیتے تھے وہ اس قسم کے اعمال کا حکم کس غرض وغایت کے ماتحت دیتا ہے.سو ہم قرآن شریف
میں دیکھتے ہیں کہ نکاح کی اغراض میں سے جو غرض مرد و عورت کے مخصوص تعلق کے ضمن میں بیان کی گئی
ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
أُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ
یعنی اے مسلمانو! فلاں فلاں قریبی رشتہ دار عورتوں کو چھوڑ کر باقی سب عورتیں تمہارے لئے
حلال اور جائز کی جاتی ہیں یہ کہ تم اپنے اموال میں سے ان کے مہر مقرر کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو.مگر تمہارے نکاح کی غرض یہ ہونی چاہئے کہ تم اس کے ذریعہ اپنے آپ کو بدیوں اور بیماریوں سے
محفوظ کر لو اور یہ غرض ہر گز نہیں ہونی چاہئے کہ تم شہوت رانی کا طریق اختیار کرو.“
اس تعلیم کا صحابہ کرام کی طبیعت پر اس قدر گہرا اثر تھا کہ اس انسان کی طرح جو ایک بات سے متاثر
ہو کر اس کے انتہائی نقطہ کی طرف جھک جاتا ہے صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہو کر عورتوں سے بالکل ہی مجتنب ہو جانے کی اجازت چاہتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جو فطرت صحیحہ کے مالک تھے اور اسلامی تعلیم کی اصل غرض و غایت کو سمجھتے ہوئے اپنے متبعین کو افراط وتفریط
کی راہوں سے بچا کر اعتدال کے مقام پر قائم رکھنا چاہتے تھے انہیں اس طریق سے باز رکھتے تھے.چنانچہ
حدیث میں آتا ہے:
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونَ
التَّبَتُلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَ خُتَصَيْنَا -
یعنی ” سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن مظعون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے عورتوں سے بالکل ہی علیحدہ ہو جانے کی اجازت چاہی مگر آپ نے اس کی اجازت نہیں دی
اور اگر آپ اجازت دے دیتے تو ہم لوگ تیار تھے کہ اپنے آپ
کو و یا بالکل خصی ہی کر لیتے.“
ان حالات میں تعیش وغیرہ کا سوال تو بالکل خارج از بحث ہے اور اس قسم کی بدظنی وہی شخص کر سکتا ہے
جو یا تو اسلامی تعلیم اور اسلامی تاریخ سے قطعی طور پر نا واقف ہوا اور یا وہ خود اس گند میں اس حد تک مبتلا ہو کہ
اسے دوسروں کے اعمال میں بھی اس گندی نیت کے سوا کوئی اور نیت نظر نہ آتی ہو.مگر بہر حال یہ سوال
قابل جواب ہے کہ لونڈیوں کے متعلق اسلامی تعلیم کیا ہے؟ سو اس کے متعلق سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہئے
ا : سورة النساء : ۲۵
: بخاری کتاب النکاح
Page 489
۴۷۴
کہ غلامی کے عام احکام میں غلام اور لونڈی کے معاملہ میں کوئی فرق نہیں ہے.یعنی جو حقوق غلاموں کے
ہیں وہی لونڈیوں کے بھی ہیں.البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ لونڈیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے اور انہیں آزاد
کر کے اپنے عقد میں لے لینے کے بارے میں اسلام نے زیادہ تاکیدی سفارش کی ہے.اور جب تک
لونڈیاں غلامی کی حالت میں رہیں اس وقت تک ان کے لئے بھی یہ پسند کیا گیا ہے کہ آزا دلوگ ان کے
ساتھ رشتے کریں تا کہ اس رشتہ دارانہ اختلاط کے نتیجے میں غلاموں کے تمدن و معاشرت میں جلد تر اصلاح
پیدا ہو سکے اور اسی غرض وغایت کے ماتحت لونڈیوں کا معاملہ تعداد ازدواج کی انتہائی حد بندی سے مستی
رکھا گیا ہے تا کہ غلاموں اور لونڈیوں کے تمدن و معاشرت میں اصلاح کے موقعے زیادہ سے زیادہ تعداد
میں کھلے رہیں اور وہ جلد تر آزاد کئے جانے کے قابل ہو جائیں.اس کے متعلق بعض قرآنی آیات اوپر
والے مضمون میں درج کی جاچکی ہیں اس جگہ ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں.یہ سوال کہ آیا لونڈیوں کے ساتھ باقاعدہ رسمی نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں.اس کی مختلف صورتیں
ہیں.اول جبکہ کسی لونڈی اور غلام کے آپس کے رشتہ کا سوال ہو.دوم جبکہ کسی لونڈی اور ایسے آزاد مرد
کے رشتہ کا سوال ہو جو اس کا مالک و آقا نہیں ہے.سوم جبکہ کسی غلام اور آزاد عورت کے رشتہ کا سوال ہو.چہارم جبکہ کسی لونڈی اور اس کے اپنے آقا و مالک کے رشتہ کا سوال ہو.ان چاروں امکانی صورتوں میں
سے پہلی تین صورتوں میں مسلمہ طور پر رسمی نکاح ضروری سمجھا گیا ہے اور اس کے بغیر رشتہ قائم نہیں ہوسکتا
لیکن چوتھی صورت میں اکثر علماء آقا اور لونڈی کے رشتے کے معاملہ میں رسمی نکاح کی ضرورت نہیں سمجھتے اور
ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ آقا کولونڈی پر حق ملکیت حاصل ہوتا ہے اس لئے قانونی رنگ میں یہی
حق نکاح کا قائم مقام سمجھا جانا چاہئے اور کسی الگ رسمی نکاح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اخلاقی اور تمدنی
اور نسلی حفاظت جو رسمی نکاح میں ملحوظ ہے وہ اس رشتہ میں بھی جو حق ملکیت کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے اسی
طرح حاصل ہوتی ہے.واللہ اعلم.قیدی عورتوں کا سوال اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ اسلام نے ان عورتوں کے متعلق بھی جو کفار
کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیں اور بطور قیدی کے
پکڑی جائیں اس قسم کا ایک استثنائی انتظام جاری کیا ہے جس کے ماتحت ان قیدی عورتوں کے ساتھ جن
کے مرد انہیں فدیہ دے کر چھڑانے کے لئے جلد نہ پہنچ جائیں یا جو قید ہونے پر خود مکاتبت کے طریق
بخاری کتاب النکاح
: سورة النساء : ۴
Page 490
۴۷۵
پر آزاد کئے جانے کا مطالبہ نہ کریں، مسلمانوں کا رشتہ نکاح قائم ہوسکتا ہے.اور اس انتظام کی غرض وغایت
اسلام نے یہ رکھی کہ تا قیدی عورتوں اور اس کی وجہ سے ان کے قید کرنے والوں کے اخلاق خراب ہونے
سے محفوظ رہیں اور سوسائٹی میں بدی اور بدکاری پھیلنے نہ پائے.تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ عموما جب کبھی بھی
کسی قوم کو کوئی بڑی جنگ پیش آئی ہے تو اس کے بعد اس قوم میں عمو مآزنا اور بدکاری کا مرض پھیل گیا
ہے.کیونکہ اول تو جنگ میں عموماً عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے.دوسرے جنگ کے مصائب کی وجہ
سے مردوں کے اعصاب پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان میں عموماً ضبط نفس کا مادہ کمزور ہو جاتا
ہے.پس چونکہ اسلام انفرادی اور قومی اخلاق کی حفاظت کے سوال
کو باقی تمام تمدنی اور معاشرتی امور پر
ترجیح دیتا ہے،اس لئے ضروری تھا کہ اس قسم کے حالات کے لئے کوئی خاص احتیاطی احکام جاری کئے
جاتے.چنانچہ ایسا کیا گیا کہ ایک طرف تو تعد دازدواج کی استثنائی اجازت دے دی گئی اور دوسری طرف
ان عورتوں کے متعلق جو ایسے جنگوں میں قید ہو کر آئیں جن میں کوئی قوم مسلمانوں کے مذہب کو برباد کرنے
کے لئے ان پر حملہ آور ہوئی ہو یہ حکم دیا گیا کہ اگر ان کے مردان کے ساتھ قید نہ ہوں اور نہ ہی وہ انہیں
چھڑانے کے لئے جلد پہنچیں اور نہ ہی یہ قیدی عورتیں خود مکاتبت کے طریق پر آزاد کئے جانے کا مطالبہ
کریں تو ان کے ساتھ مسلمانوں کو استثنائی طور پر رشتہ قائم کرنے کی اجازت ہے تا کہ نہ تو ان قیدی عورتوں
کے اخلاق خراب ہوں اور نہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں بدکاری رونما ہونے پائے اور اس
انتظام میں نسلی اختلاط و اشتباہ سے بچانے کے لئے یہ شرط لگا دی گئی کہ قیدی عورتوں کے ساتھ اس اطمینان
کے بعد رشتہ ہونا چاہئے کہ وہ حاملہ نہیں ہیں.یہ سسٹم شاید جدید تہذیب و تمدن کے دل دادگان کو
اچنبھا نظر آئے گا لیکن اگر ان حالات کو مدنظر رکھا جاوے جن کے لئے یہ انتظام مقصود ہے تو کم از کم وہ لوگ
جو انفرادی اور قومی اخلاق کی حفاظت کے خیال پر دوسرے خیالات کو قربان کرنا جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں
کہ ان حالات کے ماتحت جن میں یہ انتظام جاری کیا گیا تھا.یہ ایک بہت دانشمندانہ انتظام تھا جو بنی نوع
انسان کی حقیقی بہتری کے لئے استثنائی حالات میں ضروری سمجھا گیا.علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ
جب مکاتبت کا دروازہ ہر قیدی عورت کے لئے کھلا ہے تو جو عورت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی اس کے متعلق
یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے سابقہ رشتوں
کو قطع کر کے اسلامی سوسائٹی کا جز و بنا چاہتی ہے.پس اس حالت
میں اس کے ساتھ کسی مسلمان کا رشتہ قائم ہونا قابل اعتراض نہیں ہوسکتا.ترندی ابواب السیر صفحه ۲۹۶
Page 491
یہ سوال ہوسکتا ہے کہ عورتوں کو جنگوں میں پکڑا ہی کیوں جاتا تھا کہ اس قسم کے خطرات پیدا ہوتے.اس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانہ میں عرب میں یہ عام دستور تھا کہ عورتیں بھی کثرت کے ساتھ جنگ میں
شریک ہوتی تھیں اور بعض اوقات جنگ میں عملی حصہ بھی لیتی تھیں اور میدان جنگ میں سپاہیوں کو جوش
دلانے کا کام تو زیادہ تر عورتوں کے ہی سپرد ہوتا تھا.پس کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان حالات میں انہیں قید نہ
کیا جا تا.اگر فوجداری مقدمات میں عورت قید کی جاسکتی ہے اور ہر ایک ملک وقوم میں قید کی جاتی ہے
تو کیوں جنگجو عورت میدان جنگ میں قید نہ کی جاتی؟ علاوہ ازیں چونکہ اس زمانہ میں کفار لوگ مسلمانوں کی
عورتوں کو قید کرتے تھے بلکہ لونڈی تک بنا کر رکھتے تھے اور ان ابتدائی جنگوں میں تو ان بد باطنوں کی طرف
سے یہ عام الٹی میٹم تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو قید کر کے اپنی لونڈیاں بنائیں گے اور لونڈیوں کی طرح ان
سے تعلقات قائم کریں گے یا اس لئے خدائے اسلام نے جو اگر ایک طرف حلیم ہے تو دوسری طرف سب
سے زیادہ غیرت مند بھی ہے.مسلمانوں کو بھی اجازت دے دی کہ اگر ضرورت ہو تو وہ بھی کفار کے ساتھ
اگر ویسا نہیں تو اسی قسم کا سلوک کر کے انہیں ہوش میں لائیں تا کہ وہ اپنے مظالم میں زیادہ شوخ اور دلیر نہ
ہوتے جائیں.جنگی ضروریات سے واقف لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بسا اوقات جنگوں میں انتقامی طریق
اختیار کئے جانے کی ضرورت پیش آجاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنگی قانون سول قانون سے ہمیشہ مختلف ہوتا
ہے.پس یہ ایک ناگزیر حالات کی مجبوری تھی جس کے بغیر چارہ نہیں تھا اور جب یہ صورت حال پیدا ہوگئی
کہ عورتیں قید میں آتی تھیں اور نیز یہ کہ کفار لوگ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہر قسم کا سلوک روا ر کھتے تھے تو
اس کے لازمی اور خطرناک نتائج کے سدباب کے لئے کوئی خاص قانون جاری کرنا بھی ضروری تھا.البتہ
چونکہ موجودہ زمانہ میں کفار لوگ مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کرتے اور اگر عورتیں قید بھی ہوں
تو انہیں شاہی قیدی کے طور پر رکھا جاتا ہے اس لئے اصولی قرآنی حکم کے مطابق جو او پر درج کیا گیا ہے
اس زمانہ میں مسلمانوں کے لئے بھی یہ نا جائز ہوگا کہ وہ کفار کی عورتوں کو بلا کسی حقیقی مجبوری کے قید کریں یا
قید کرنے کے بعد انہیں مسلمانوں کی انفرادی حراست میں دے کر کوئی رنگ غلامی کا پیدا کریں.اس جگہ اگر کسی کو شبہ پیدا ہو کہ ایسا کیوں ہے کہ بعض حالات میں شریعت اسلامی کا فتویٰ اور ہوتا ہے
اور بعض میں اور تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی نقص کی بات نہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو یہی بات اسلامی
شریعت کے کامل اور عالمگیر ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت میں
ابوداؤ د کتاب جہا د باب في خبر النفير
۲: چشمه معرفت صفحه ۲۴۵
Page 492
حالات کے اختلاف کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے اور جہاں بعض احکام جو اصل الاصول کے طور پر ہیں
ٹھوس اور غیر مبدل صورت میں رکھے گئے ہیں جن میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں وہاں بہت سے احکام
ایسے بھی ہیں جن میں یا تو حالات کے اختلاف سے حکم کی صورت بدل جاتی ہے اور یا ان میں مختلف حالات
کے ماتحت نئی مگر جائز تشریحات کی گنجائش ہوتی ہے.چنانچہ قرآن شریف خود فرماتا ہے:
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ مِنْهُ أَيتُ مُحْكَمْتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَشْبِهُنَّ ا
یعنی ”خدا نے یہ قرآن شریف اس صورت میں اتارا ہے کہ اس کی بعض آیات تو محکم ہیں
یعنی اصل الاصول کے طور پر ہیں جو سب حالات میں ایک سی چسپاں ہوتی ہیں اور بعض متشابہات
ہیں یعنی ان میں ایسی لچک رکھی گئی ہے کہ وہ مختلف حالات میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی مختلف
صورتیں اختیار کر سکتی ہیں.“
خلاصہ کلام یہ کہ غلامی کے متعلق اسلامی تعلیم دو حصوں میں منقسم ہے.اوّل وہ تعلیم جو ان لوگوں سے
تعلق رکھتی ہے جو کسی وجہ سے ظالمانہ غلامی کے چکر میں آچکے تھے اور ان کے اخلاق و عادات میں
عموماً نہایت درجہ پستی اور دنائت پیدا ہو چکی تھی اور وہ جو ہر جو انسان کو دنیا میں آزاد زندگی گزارنے کے
قابل بناتا ہے ان میں مفقود ہو چکا تھا.ایسے لوگوں کے متعلق اسلام نے یہ تجویز کی کہ پہلے ان کے اخلاق
اور تمدن کو درست کیا جاوے اور پھر جوں جوں ان کی اصلاح ہوتی جاوے وہ ساتھ ساتھ آزاد کئے جاتے
رہیں اور ایسا انتظام کیا کہ آزاد ہونے کے بعد ایسے لوگوں کی آزادی حقیقی آزادی ہو نہ کہ محض رسمی اور نمائش
کی آزادی اور اس انتظام کی نگرانی کا کام اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل کر دیا گیا تا کہ لوگ اس
معاملہ میں کسی قسم کی سنتی یا غفلت سے کام نہ لیں.دوم وہ تعلیم جو غلام بنانے کے سوال کے متعلق اسلام
نے اصولی طور پر دی اور جس کی رو سے غلامی کے تمام ظالمانہ طریق قطعی طور پر منسوخ کر دئے گئے.باقی
رہا جنگی قیدیوں کا سوال سواس میں بے شک بعض حالتوں میں انتظامی طریق پر غلامی کی اجازت دی گئی
ہے مگر اس کی تفصیلات پر غور کیا جاوے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس رنگ کی غلامی نہیں ہے جو
غیر اسلامی دنیا میں عام طور پر معروف ہے بلکہ حقیقتا ایک نوع قید کی ہے اور یہ جوابی اور غیر حقیقی غلامی بھی
جس کی اجازت دی گئی ہے موجودہ زمانہ میں ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اب شاہی قید خانوں کا سسٹم رائج
ہو گیا ہے اور کفار مسلمانوں کے قیدیوں کو غلام نہیں بناتے بلکہ شاہی قیدیوں کے طور پر رکھتے ہیں.اس لئے
: سورة آل عمران : ۸
Page 493
CLA
اب مسلمانوں کے لئے بھی ناجائز ہے کہ کفار کے قیدیوں کو مسلمانوں کی انفرادی حراست میں تقسیم کر کے
کوئی رنگ غلامی کا پیدا کریں.باقی رہا غلاموں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا معاملہ سواس میں
اسلام نے وہ منصفانہ اور محسنانہ تعلیم دی ہے کہ جس کی نظیر کوئی قوم کسی زمانہ میں پیش نہیں کر سکتی.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَبَارِک وَسَلَّمْ
Page 494
حضرت عائشہ کا رخصتانہ اور ان کی عمر کی بحث
تعدد ازدواج کا مسئلہ.دو فرضی واقعات
حضرت عائشہؓ کا رخصتانہ، ماہ شوال ۲ ہجری کتاب کے حصہ اول میں یہ ذکر گذر چکا ہے.حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کے ساتھ شادی فرمائی تھی یہ سنہ نبوی کا دسواں سال اور شوال کا مہینہ
تھا.اور اُس وقت حضرت عائشہ کی عمر سات سال کی تھی یہ مگر معلوم ہوتا ہے کہ اُن کا نشو ونما اس وقت بھی
غیر معمولی طور پر اچھا تھا؛ ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ خولہ بنت حکیم کو جو ان کے نکاح کی محرک بنی تھیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے لیے اُن کی طرف خیال جاتا لیکن بہر حال ابھی تک وہ بالغ نہیں
ہوئی تھیں، اس لیے اُس وقت نکاح تو ہو گیا مگر رخصتانہ نہیں ہوا اور وہ بدستور اپنے والدین کے پاس مقیم
رہیں ، لیکن اب ہجرت کے دوسرے سال جب کہ اُن کی شادی پر پانچ سال گذر چکے تھے اور ان کی عمر
بارہ سال کی تھی وہ بالغ ہو چکی تھیں ، چنانچہ خود حضرت ابو بکر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہو کر رخصتانہ کی تحریک کی.جس پر آپ نے مہر کی ادائیگی کا انتظام کیا.(اس زمانہ میں مہر کے
نقد ادا کرنے کا دستور تھا.) اور ماہ شوال ۲ ہجری میں حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر سے رخصت ہوکر
حرم نبوی میں داخل ہو گئیں.یہ سوال کہ رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی اس زمانہ میں ایک اختلافی سوال بن گیا ہے.عام کتب تاریخ اور کتب حدیث میں حضرت عائشہ کی عمر نو یا دس سال کی بیان ہوئی ہے حتی کہ صحیح بخاری میں
خود حضرت عائشہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ رخصتانہ کے وقت میری عمر صرف نو سال
تھی اور اسی بنا پر
: استیعاب صفحه ۷۶۵ سطر ۷، ۸
: ابن ہشام جلد ۳ ذکر ازواج النبی
طبرانی بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۳۱ ۴: عینی جلد اصفحه ۴۵
Page 495
۴۸۰
جمہور مؤرخین نے نو سال کی عمر بیان کی ہے مگر اس کے مقابلہ میں بعض جدید محققین نے مختلف قسم کے
استدلالات سے چودہ سال بلکہ سولہ سال تک عمر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے.ہر چند کہ ہم ان نو محققین کی
رائے سے اتفاق نہیں رکھتے مگر حالات کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے کہ نو سال کی عمر کا خیال بھی درست نہیں
ہے.بلکہ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر پورے بارہ سال یا قریباً
بارہ سال کی ثابت ہوتی ہے.دراصل اس معاملہ میں متقدمین کو تو ساری غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ انہوں
نے حضرت عائشہ کے نو سال والے اندازے کو جو صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے بالکل یقینی اور قطعی سمجھ کر
کسی اور بات کی طرف توجہ نہیں کی ؛ حالانکہ ہر عقلمند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ روایت کا صحیح ہونا اور بات ہے اور
اندازے کا صحیح ہونا بالکل اور بات یعنی باوجود اس کے کہ یہ روائتیں جن میں حضرت عائشہ کا یہ اندازہ بیان
ہوا ہے کہ رخصتانہ کے وقت میری عمر نو سال کی تھی اصل روایت کے لحاظ سے بالکل صحیح ہوں.حضرت
عائشہ کا یہ اندازہ خود اپنی ذات میں غلط ہو سکتا ہے.جیسا کہ بسا اوقات لوگوں کے اندازے اپنی عمر کے
متعلق غلط ہو جایا کرتے ہیں.اس کے مقابلہ میں جن لوگوں نے نو سال والے خیال کو غلط سمجھ کر آزادانہ
تحقیق کرنی چاہی ہے انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ تحقیق کے سید ھے اور صاف راستہ کو ترک کر کے ایک ایسا
پیچیدہ طریق اختیار کیا ہے کہ جو دل کی تسلی کا موجب نہیں ہوسکتا.ہر فہمید شخص ہمارے ساتھ اتفاق کرے گا
کہ سب سے زیادہ پختہ اور سب سے زیادہ آسان ذریعہ حضرت عائشہ کی عمر کا پتہ لگانے کا یہ ہے کہ ہمیں
ایک طرف تو ان کی پیدائش کی تاریخ اور دوسری طرف ان کے رخصتانہ کی تاریخ کا پتہ چل جاوے کیونکہ
ان دونوں تاریخوں کے معین ہو جانے کے بعد رخصتانہ کے وقت کی عمر کے متعلق کسی شک و شبہ کی گنجائش
نہیں رہ سکتی.پہلے ہم پیدائش کے سوال کو لیتے ہیں.ابن سعد نے طبقات میں یہ روایت نقل کی ہے کہ گانت
عَائِشَةُ وَلَدَتِ السَّنَةَ الرَّابِعَةَ مِنَ النُّبوَةِ فِى اَوَّلِهَا - یعنی حضرت عائشہ" ہم نبوی کے ابتدا میں پیدا
ہوئیں تھیں.حضرت عائشہ کی تاریخ پیدائش کے متعلق اس روایت کے سوا کوئی اور معین روایت ابتدائی
مؤرخین کی کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گذری اور نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی
روایت آتی ہے.پس پیدائش کی تاریخ تو آسانی کے ساتھ معین ہوگئی اور وہ ابتدا ۴ نبوی ہے.اب ہم دوسرے سوال کو لیتے ہیں جو رخصت نہ کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے.اس میں بیشک روایات میں
اختلاف ہے.بعض روایات میں یہ تاریخ شوال اہجری بیان ہوئی ہے اور بعض میں شوال ۲ ہجری لیکن غور
: طبقات ابن سعد جلد ۸ صفحه ۵۴
Page 496
۴۸۱
کیا جاوے تو مؤخر الذکر روایات زیادہ صحیح قرار پاتی ہیں.شوال اہجری والی روایت کا اصل منبع ابن سعد
ہے جس نے ایک سلسلہ رواۃ کے ذریعہ اس روایت کو حضرت عائشہ تک پہنچایا ہے.اور اکثر مورخین نے
ابن سعد والی روایت پر ہی بنا رکھ کر رخصتانہ کی تاریخ شوال اہجری قرار دی ہے لیکن گوا بن سعد خود اپنی
ذات میں ثقہ ہے مگر اس روایت میں اس کے راویوں میں ایک راوی واقدی ہے جس کے غیر ثقہ اور
نا قابل اعتماد بلکہ جھوٹا ہونے کے متعلق محققین نے قریباً قریباً اجماع کیا ہے.پس محض اس واقدی والی
روایت پر جبکہ وہ دوسری روایات کے خلاف ہو ایک تاریخی واقعہ کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی.اس کے مقابلہ پر
علامہ نووی علامہ عینی اور قسطلانی اور بعض دوسرے محققین نے شوال ۲ ہجری والی روایت کو صحیح اور قابل ترجیح
قرار دیا ہے..اور علامہ نووی نے تو بڑی صراحت اور اصرار کے ساتھ لکھا ہے کہ اس روایت کے مقابلہ
میں شوال اہجری والی روایت کمزور اور قابل رد ہے.پس کوئی وجہ نہیں کہ صرف اس بنا پر کہ عام مؤرخین
نے شوال ۱ہجری والی روایت کی تقلید کی ہے ہم ایک زیادہ مضبوط خیال کو رد کر دیں اور دراصل عام
مؤرخین نے بھی واقدی کی روایت کو محض اس خیال سے نوازا ہے کہ وہ نو سال والی عمر کے اندازے کے
ساتھ جو صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے زیادہ مطابقت کھاتی ہے، چنانچہ زرقانی جیسا محقق صاف
لکھتا ہے کہ شوال ۲ ہجری والی روایت اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس طرح نو سال سے زیادہ ہو جاتی
ہے.حالانکہ جب خود عمر کا سوال اور عمر کی روایتیں ہی زیر بحث ہوں تو کسی خاص روایت کو صحیح فرض کر لینا
درست نہیں ہے اور پھر جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں نو سال والے اندازے کو غلط ماننے کے یہ معنے
نہیں ہیں کہ نو سال والی روایتیں بھی غلط ہیں اور پھر تعجب یہ ہے کہ خود علامہ زرقانی نے دوسری جگہ 2
شوال ۲ ہجری والے قول کو مقدم کیا ہے.اندریں حالات شوال اہجری والی روایت شوال ۲ ہجری والی روایت
کے مقابلہ میں قابل قبول نہیں مجھی جاسکتی اور حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کا رخصتانہ شوال ۲ ہجری
میں ہوا تھا.واللہ اعلم
اب جب پیدائش اور رخصتانہ کی تاریخوں کی تعیین ہوگی تو عمرکا پتہ لگا نا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ یہ
: طبقات جلد ۸ صفحه ۴۰،۳۹
: تہذیب التہذیب جلد ۹ صفحه ۳۶۶ تا ۳۶۸
سے : نووی بحوالہ زرقانی جلد اصفحه ۴ ۳۷ وجلد ۳ صفحه ۲۳۰.عینی شرح بخاری جلد اصفحہ۴۵.مواہب اللہ نیہ ذکر حضرت عائشہ و
تاریخ یا فعی اور وفا واسدالغابہ بحوالہ میں جلد اصفحه ۴۰۳
۴، ۵ : زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۳۰
زرقانی جلد ۲ صفحه و جلد ۳ صفحه ۲۰۳
Page 497
۴۸۲
صرف ایک موٹا حسابی سوال رہ جاتا ہے جسے ایک بچہ بھی نکال سکتا ہے.حضرت عائشہ ۴ نبوی کے شروع
میں پیدا ہوئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ۱۴ نبوی کے ربیع الاوّل میں ہوئی.اس طرح
ہجرت تک حضرت عائشہ کی عمر کچھ ماہ اوپر دس سال بنتی ہے اور ہجرت کے بعد جو ربیع الاول اہجری میں
ہوئی شوال ۲ ہجری تک جبکہ حضرت عائشہؓ کا رخصتانہ ہوا دو سال سے کچھ کم کا عرصہ ہوتا ہے اور ان دونوں
عرصوں کو ملانے سے وہی بارہ سال حاصل ہوتے ہیں جو ہم نے ابتداء میں بیان کئے ہیں اور اگر ابن سعد
کی روایت کے مطابق رخصتانہ کو ہجرت کے پہلے سال میں سمجھا جاوے تو پھر بھی یہ عرصہ گیارہ سال کا بنتا
ہے نہ کہ نو یا دس سال کا اور یہ ایک حسابی نتیجہ ہے جس کے مقابلہ میں کوئی تخمینی اندازہ قبول نہیں کیا جاسکتا.اب رہا یہ سوال کہ متعدد احادیث میں حضرت عائشہ نے خود اپنی عمر نو سال کی کیوں بیان کی ہے؟
سواس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان روایتوں کو غلط نہیں کہتے یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا یہی خیال
تھا کہ رخصتانہ کے وقت ان کی عمر نو سال
کی تھی لیکن یقیناً ان کا یہ خیال محض تخمینی تھا اور درست نہیں تھا اور یہ
کوئی قابل تعجب بات نہیں کیونکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ عمروں کے اندازوں میں لوگوں سے غلطی ہو جایا کرتی
ہے.پس اگر پیدائش اور رخصتانہ کی تاریخوں کے حسابی مقابلہ سے حضرت عائشہ کی عمر نو سال نہیں بنتی تو
محض حضرت عائشہ کے اس اندازے کی وجہ سے کہ رخصتانہ کے وقت میری عمر نو سال کی تھی نو سال والی
روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا؛ البتہ اگر کسی صحیح حدیث میں حضرت عائشہ کی پیدائش کی تاریخ اوائل ۴ نبوی
کے علاوہ کوئی اور بیان کی گئی ہو یا رخصتانہ کی تاریخ شوال ۲ ہجری کے علاوہ کوئی اور ثابت ہو تو بیشک یہ
روایتیں قابل قبول ہوں گی اور انہی پر عمر کے حساب
کو مینی قرار دیا جائے گا لیکن ایک محض اندازے اور خیال
کے مقابلہ میں خواہ وہ صحیح احادیث میں ہی بیان کیا گیا ہو ایک حسابی نتیجہ کور دنہیں کیا جاسکتا.یہ تو ایک اصولی بحث ہے جو ہم نے اس جگہ پیش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اندازے والی
روایتوں کی چھان بین کی جائے تو ان سے بھی بالآخر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی یہ کہ
رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر بارہ سال کی تھی نہ کہ نو سال کی.اس کے سمجھنے کے لیے یہ جاننا
ضروری ہے کہ دراصل حضرت عائشہ نے صرف رخصتانہ کی عمر کا اندازہ ہی نہیں بتایا بلکہ ساتھ ہی نکاح کی عمر
کا اندازہ بھی بتایا ہے اور حدیث و تاریخ کی کتابوں میں یہ دونوں اندازے ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں؛
چنانچہ حضرت عائشہ کا یہ قول کثرت کے ساتھ مروی ہوا ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر چھ یا سات
: طبری جلد ۳ صفحه ۱۲۵۵ و تاریخ خمیس جلد اصفحه ۳۶۴۲۶۳
Page 498
۴۸۳
سال
کی تھی اور جب میرا رخصتانہ ہوا تو میری عمر نو سال کی تھی اور بعض روایتوں میں رخصتانہ کی عمر دس سال
بھی بیان ہوئی ہے.اب اصولی قاعدہ کے مطابق ہمیں ان دونوں اندازوں میں سے پہلے اندازے کو جو
نکاح کے وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اقرب بالصحت سمجھنا چاہئے.کیونکہ اول تو یہ اندازہ زیادہ چھوٹی عمر
کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جبکہ غلطی کا امکان نسبتاً کم ہوتا ہے.دوسرے چونکہ وہ سب سے پہلا اندازہ ہے.وہی اصل اندازہ سمجھا جائے گا اور بعد کی عمر کے ساتھ تعلق رکھنے والے اندازے اس اندازے کی فرع سمجھے
جائیں گے نہ کہ مستقل اندازے.پس اندازوں کی بحث میں اصل بنیاد لا زما پہلے اندازے پر رکھی جائے
گی جو نکاح کے وقت کی عمر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس میں چھ یا سات سال کی عمر بیان کی گئی ہے.اب
جب ہم اس اندازے سے حساب شماری کر کے رخصتانہ کی عمر کا پتہ لگاتے ہیں تو اس طرح بھی وہی بارہ
سال کی عمر ثابت ہوتی ہے نہ کہ نو یا دس سال کی مگر پیشتر اس کے کہ ہم یہ حساب پیش کریں چھ اور سات کے
باہمی اختلاف کا حل ضروری ہے.یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ شادی کے وقت کی عمر بعض روایتوں میں چھ سال
بیان ہوئی ہے اور بعض میں سات سال اور یہ دونوں قسم کی روایتیں کتب حدیث اور کتب تاریخ ہر دو میں
پائی جاتی ہیں.سات سال والی روایت خصوصیت کے ساتھ صحیح مسلم ونسائی اور ابن ہشام اور ابن سعد
اور طبری ج میں بیان ہوئی اور اس کے مقابلہ میں چھ سال والی روایت بھی ان سب کتب میں باستثنا
سیرت ابن ہشام مروی ہوئی ہے اور علاوہ اس کے بخاری میں بھی چھ سال والی روایت پائی جاتی ہے.اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی روایتوں میں سے کونسی روایتیں قابل ترجیح ہیں.ہر شخص جو علم
روایت سے تھوڑا بہت بھی مس رکھتا ہے اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جہاں تک محض روایت کی صحت کا تعلق.کہ دونوں قسم کی روایتیں ہر طرح صحیح اور قابل اعتماد ہیں اور ہم ان میں سے کسی کو غلط کہ کر رد نہیں کر سکتے.پس ماننا پڑے گا کہ خود حضرت عائشہ نے ہی مختلف موقعوں پر یہ دو مختلف اندازے بیان کیے ہیں.یعنی کبھی
تو انہوں نے اپنی عمر چھ سال کی بیان کی ہے اور کبھی سات سال کی اور کبھی ان دونوں کو ملا کر یہ کہ دیا ہے کہ
شادی کے وقت میری عمر چھ یا سات سال
کی تھی.پس روایت کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن درایتاً
غور کیا جاوے تو سات سال والے اندازے کو ترجیح دینی پڑتی ہے اور وہ اس طرح پر کہ یہ ایک عام دستور
ہے کہ جب تک عمر کا کوئی سال پورا نہیں ہو جاتا.اس وقت تک صرف نیچے کے سال کا نام لیا جاتا ہے اور
ا : بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۳۰
۲ : ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۴
: ابن سعد جلد ۸ صفحه ۴۱ سطر ۲۶
: طبری جلد ۳ صفحه ۲۶۳ ۱ سطری
ہے
Page 499
۴۸۴
اوپر کی کسر کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اوپر کے سال کا نام صرف اسی وقت لیا جاتا ہے کہ جبکہ یا تو اوپر کا سال پورا
ہو چکا ہو اور یا پورا ہونے کے اس قدر قریب ہو کہ عملاً اسے پورا سمجھا جا سکے.پس حضرت عائشہ کی عمر کے
متعلق بعض روایات میں چھ سال کا ذکر آنا اور بعض میں سات سال کا یقینی طور پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے
کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر چھ سے گذر کے سات کے اس قدر قریب پہنچ چکی تھی کہ اس پر سات
سال کا اطلاق عام محاورہ کی رو سے جائز ہو گیا تھا اور صرف تھوڑی سی برائے نام کمی کی وجہ سے چھ سال کا
لفظ استعمال کر لیا جاتا تھاور نہ عمل ان کی عمر سات سال کی ہی تھی ، چنا نچہ اسی خیال کے ماتحت بعض مؤرخین
نے چھ سال کے ذکر کو بالکل ترک کر دیا ہے اور صرف سات سال کا ذکر کیا ہے مثلاً ابن ہشام نے چھ
سال کا ذکر تک نہیں کیا اور صرف سات سال کا ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلہ میں میری نظر سے کوئی ایسی
مستند تاریخ کی کتاب نہیں گذری جس میں صرف چھ سال کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا ہو.پھر صاحب سیرت
حلبیہ نے بھی جہاں ازواج النبی کا ذکر کیا ہے، وہاں حضرت عائشہ کی عمر صرف سات سال بیان کی ہے اور
چھ سال کا ذکر نہیں کیا.اور حضرت عائشہ کے نکاح کے بیان میں ذکر تو دونوں کا ہے مگر صراحنا لکھا ہے کہ
سات سال والی روایت اقرب بالصحت ہے.اندریں حالات گوروایتاً دونوں قسم کی روایتیں صحیح ہیں مگر
درایت کے طریق پر اس بات میں کسی قسم کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں کبھی جاسکتی کہ نکاح کے وقت حضرت
عائشہ کی عمر سات سال کے اس قدر قریب پہنچی ہوئی تھی کہ گویا عملا وہ سات سال ہی تھی.اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر سات سال
کی تھی تو اگلا حساب کوئی
مشکل کام نہیں رہتا.یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی شوال ۱۰ نبوی میں ہوئی تھی.اور یہی
تاریخ جمہور مؤرخین میں مسلم ہے گویا شوال ۱۰ نبوی میں حضرت عائشہ کی عمر سات سال یا اس کے قریب
تھی.اس کے بعد ربیع الاول ۱۴ نبوی میں ہجرت ہوئی.اس طرح شادی اور ہجرت کے درمیان کا
عرصہ تین سال اور کچھ ماہ بنتا ہے اور ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر دس سال اور کچھ ماہ کی قرار پاتی
ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت اور رخصتانہ کے درمیان کا عرصہ کس قدر ہے.یہ مسلم ہے کہ ہجرت
ربیع الاوّل میں ہوئی ، اس لیے ہجرت کا پہلا سال ساڑھے نو ماہ کا ہوا اور پھر چونکہ رخصتا نہ شوال ۲ ہجری
میں ہوا اس لیے ساڑھے نو ماہ ہی دوسرے سال کے ہوئے اور یہ دونوں عرصے مل کر ہجرت اور رخصتانہ
ا : ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۴
سیرت حلبیہ جلد ۳ صفحه ۳۵۲
: ابن سعد جلد ۸ صفحه ۳۹ ۵ : طبری جلد ۳ صفحه ۱۲۵۵
: سیرت حلبیہ جلد ۱ صفحه ۳۷۹
Page 500
۴۸۵
کے درمیان کا عرصہ انہیں ماہ یعنی ایک سال اور سات ماہ کا ہوا.اب اگر اس عرصہ کو دس سال اور کچھ ماہ کے
عرصہ کے ساتھ ملا ئیں جو ہجرت سے قبل کا ہے تو اس کی میزان وہی بارہ سال ہوتی ہے جو ہم نے دوسری
جہت سے قرار دی ہے.خلاصہ کلام یہ کہ خواہ حضرت عائشہؓ کے اندازے سے حساب شماری کریں یا یہ کہ ان
کی تاریخ پیدائش سے شمار کریں نتیجہ دونوں صورتوں کا یہی ہے کہ رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر
بارہ سال کی تھی نہ کہ نو سال کی اور یقیناً حضرت عائشہ کا یہ خیال کہ اُس وقت میری عمر نو سال کی تھی غلط
اندازے یا غلط حساب شماری پر بنی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مہینوں کی کسر چھوڑ کر اپنے
نکاح کی عمر کا اندازہ چھ سال لگایا تو اس کے بعد انہوں نے حسابی طور پر درمیانی عرصہ کو مار نہیں کیا بلکہ یونہی
موٹے طور پر اندازہ کر لیا کہ رخصتانہ کے وقت ان کی عمر نو سال کی ہوگی اور پھر یہی خیال ان کے دل میں
قائم ہو گیا.یا یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ اس وقت تک ابھی جنتری وغیرہ کا حساب مروج نہیں ہوا تھا اور ہجری
کی تاریخ بھی ابھی ضبط و تدوین میں نہیں آئی تھی اور پھر شادی اور رخصتانہ کے درمیان کی میعاد بھی دو
مختلف سنین ( یعنی سن نبوی اور سن ہجری) کے حسابات سے تعلق رکھتی تھی اس لیے حضرت عائشہ سے حساب
شماری میں سہوا غلطی ہوگئی ہو اور پھر یہ غلط خیال ان کے دل میں ایسا راسخ ہو گیا ہو کہ بعد میں
کبھی اس حسابی
غلطی کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہ ہوا ہو لیکن بہر حال کچھ بھی ہو اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ نکاح کے وقت
حضرت عائشہ کی عمر سات سال یا اس کے قریب تھی تو پھر رخصتانہ کے وقت نو سال کی عمر کا اندازہ کسی
صورت میں بھی درست نہیں سمجھا جا سکتا اور یہ ایک حسابی سوال ہے جس کے مقابلہ میں کوئی اور دلیل نہیں
ٹھہر سکتی.خلاصہ کلام یہ کہ خواہ کسی جہت سے بھی دیکھا جاوے رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر بارہ
سال یا اس کے قریب قریب ہوتی ہے اور اگر رخصتانہ کی تاریخ شوال اہجری قرار دی جاوے تو پھر بھی ان
کی عمر گیارہ سال کی بنتی ہے.پس نو سال کا اندازہ بہر حال غلط اور نا درست ہے.لیکن اگر بالفرض نو سال کی عمر کو ہی صحیح تسلیم کر لیا جاوے تو پھر بھی کوئی جائے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ
عرب جیسے ملک میں نو یا دس سال کی لڑکی کا بالغ ہو جانا بعید از قیاس نہیں.خود ہمارے ہندوستان میں بھی
بعض لڑکیاں جن میں نشو و نما کا مادہ غیر معمولی طور پر زیادہ ہوتا ہے.دس سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں.دراصل بلوغ کا انحصار زیادہ تر آب و ہوا اور خوراک اور گردو پیش کے حالات پر ہوتا ہے.ٹھنڈے ممالک
میں اور خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں کی خوراک میں گرم مسالہ جات کا دخل کم ہوتا ہے لڑکیاں عموماً بہت
دیر میں بالغ ہوتی ہیں؛ چنانچہ انگلستان وغیرہ میں سن بلوغ اوسطاً اٹھارہ سال کا ہوتا ہے اورلڑکیوں کی
Page 501
۴۸۶
شادی عموماً بیس سال بلکہ بسا اوقات اس سے بھی زیادہ عمر میں ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی
ہیں سال کی عمر تک بغیر شادی کے بیٹھی رہے تو عموماً لوگوں میں انگشت نمائی شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں
کوئی نقص ہوگا تبھی اسے کوئی رشتہ نہیں ملا کیونکہ یہاں بلوغ کی اوسط عمر تیرہ چودہ سال ہے.عرب کا ملک
چونکہ ہندوستان کی نسبت بھی زیادہ گرم اور خشک ہے اس لیے وہاں کے سن بلوغ کی اوسط ہندوستان سے بھی
گری ہوئی ہے اور کئی لڑکیاں ایسی ملتی ہیں جو نو دس سال
کی عمر میں ہی سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں.اندریں حالات
حضرت عائشہ کا نو یا دس سال کی عمر میں بالغ ہو کر رخصتانہ کے قابل ہو جانا ہرگز قابلِ تعجب نہیں سمجھا جاسکتا.خصوصاً جبکہ اس امر کو مد نظر رکھا جاوے کہ حضرت عائشہ میں نشو و نما کا مادہ غیر معمولی طور پر زیادہ تھا.جیسا کہ سرولیم میور نے بھی اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے.بہر حال اب حضرت عائشہ پوری طرح بالغ تھیں اور ہجرت کے بعد شوال ۲ ہجری میں ان کا رخصتانہ
ہوا.اس وقت حضرت عائشہ کی والدہ مدینہ کے مضافات میں ایک جگہ الشنع نامی میں مقیم تھیں ؛ چنانچہ
انصار کی عورتوں نے وہاں جمع ہو کر حضرت عائشہ کو رخصتانہ کے لیے آراستہ کیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر حرم نبوی میں
داخل ہو گئیں..مہر پانچ سو درہم کیا بعض روایات کی رو سے چار سو درہم یعنی کم و بیش یک صد روپیہ تھا
جو رخصتانہ کے وقت نقد ادا کر دیا گیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے صرف حضرت
عائشہ ہی وہ بیوی تھیں جو باکرہ ہونے کی حالت میں آپ کے نکاح میں آئیں.باقی سب بیوہ یا مطلقہ
تھیں اور اس خصوصیت کو حضرت عائشہ بعض اوقات اپنے امتیازات میں شمار کیا کرتی تھیں.حضرت عائشہ
کے رخصتانہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً پچپن سال کی تھی اور آپ حضرت عائشہ کی
خوردسالی کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہت دلداری کا سلوک فرماتے اور ان کے جذبات کا خاص
خیال رکھتے تھے ، چنانچہ ایک دفعہ جب چند حبشی شمشیر زن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو
نیزہ کے کرتب دکھانے لگے تو آپ نے انہیں مسجد نبوی کے صحن میں کرتب دکھانے کے لیے ارشاد فرمایا
اور خود حضرت عائشہ کو سہارا دے کر مکان کی دیوار کے ساتھ اپنی اوٹ میں لے کر کھڑے ہو گئے تا کہ وہ
بھی ان لوگوں کے کرتب دیکھ لیں اور جب تک وہ اس فوجی تماشہ سے خود سیر نہیں ہو گئیں آپ وہاں سے
: دیکھو لائف آف محمد صفحه ۱۷۱۱۱۰ : بخاری کتاب بدء الخلق نتز و پیج النبی
: ابن سعد
۵ : ابن سعد
مسلم
: بخاری کتاب النکاح
Page 502
۴۸۷
نہیں ہے.ایک دوسرے موقع پر آپ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا.پہلی دفعہ تو
حضرت عائشہ آگے نکل گئیں لیکن جب ایک عرصہ بعد آپ دوسری دفعہ ان کے ساتھ دوڑے تو اس وقت وہ
پیچھے رہ گئیں جس پر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا.ھذہ بتلگ یعنی ”لو عائشہ اب وہ بدلہ اتر گیا
ہے.‘، بعض اوقات حضرت عائشہ کی بعض سہیلیاں اُن کے گھر میں معصومانہ اشعار وغیرہ پڑھنے کا شغل
کرتیں ، تو آپ بالکل تعرض نہ فرماتے بلکہ جب ایک دفعہ حضرت ابوبکر نے یہ نظارہ دیکھ کر لڑکیوں کو
کچھ تنبیہ کرنی چاہی تو آپ نے منع فرمایا اور کہا ابو بکر جانے دو.یہ عید کا دن ہے لڑکیاں اپنا شغل کرتی ہیں
لیکن جب آپ دوسری طرف متوجہ ہوئے تو حضرت عائشہ نے خود لڑکیوں کو اشارہ کر کے انہیں رخصت کر
دیا.مگر با وجود اس صغرسنی کے حضرت عائشہ کا ذہن اور حافظہ غضب کا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیم و تربیت کے ماتحت انہوں نے نہایت سرعت کے ساتھ حیرت انگیز طور پر ترقی کی اور دراصل اس
چھوٹی عمر میں ان کو اپنے گھر میں لے آنے سے آپ کی غرض ہی یہ تھی کہ تا آپ بچپن سے ہی اپنے منشا
کے مطابق ان کی تربیت کر سکیں اور تا انہیں آپ کی صحبت میں رہنے کا لمبے سے لمبا عرصہ مل سکے اور وہ اس
نازک اور عظیم الشان کام کے اہل بنائی جاسکیں جو ایک شارع نبی کی بیوی پر عاید ہوتا ہے، چنانچہ آپ
اس منشا میں کامیاب ہوئے اور حضرت عائشہ نے مسلمان خواتین کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا وہ کام سرانجام
دیا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی.احادیث نبوی کا ایک بہت بڑا اور بہت ضروری حصہ حضرت عائشہ
ہی کی روایات پر مبنی ہے حتی کہ ان کی روایتوں کی کل تعداد دو ہزار دوسو دس تک پہنچتی ہے.ان کے علم وفضل
اور تفقہ فی الدین کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کا لوہا مانتے اور ان سے فیض حاصل کرتے
تھے.حتی کہ حدیث میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحا بہ کو کوئی علمی مشکل ایسی پیش
نہیں آئی کہ اس کا حل حضرت عائشہ کے پاس نہ مل گیا ہو اور عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے کوئی
نص علم قرآن اور علم میراث اور علم حلال و حرام اور علم فقہ اور علم شعر اور علم طب اور علم حدیث عرب اور
علم انساب میں عائشہ سے زیادہ عالم نہیں دیکھا.زہد و قناعت میں ان
کا یہ مرتبہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے
پاس کہیں سے ایک لاکھ درہم آئے انہوں نے شام ہونے سے پہلے پہلے سب خیرات کر دیے ! حالانکہ گھر
: بخاری باب حسن المعاشرت
۱۳ : بخاری کتاب العیدین
۵ : ترندی مناقب عائشہ.کے ابودا ودباب السبق
۴ : زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۳۴
حاکم وطبرانی بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۳۴
Page 503
۴۸۸
میں شام کے کھانے تک کے لیے کچھ نہیں تھا.انہی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے جن کی جھلک آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی نظر آنے لگ گئی تھی.آپ انہیں خاص طور پر عزیز رکھتے تھے اور بعض
اوقات فرماتے تھے کہ سب لوگوں میں عائشہ مجھے محبوب ترین ہے.ایک دفعہ فرمایا کہ مردوں میں تو بہت
لوگ کامل گذرے ہیں لیکن عورتوں میں کا ملات بہت کم ہوئی ہیں.پھر آپ نے آسیہ اہلیہ فرعون اور
مریم بنت عمران کا نام لیا اور پھر فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں پر وہ درجہ حاصل ہے جو عرب کے بہترین کھانے
ترید کو دوسرے کھانوں پر ہوتا ہے.ایک دفعہ بعض دوسری ازواج مطہرات نے کسی اہلی امر میں
حضرت عائشہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کہی مگر آپ خاموش رہے لیکن جب
اصرار کے ساتھ کہا گیا تو آپ نے فرمایا ” میں تمہاری ان شکایتوں کا کیا کروں میں تو یہ جانتا ہوں کہ کبھی
کسی بیوی کے لحاف میں مجھ پر میرے خدا کی وحی نازل نہیں ہوئی ،مگر عائشہ کے لحاف میں وہ ہمیشہ
نازل ہوتی ہے.اللہ اللہ ! کیا ہی مقدس وہ بیوی تھی جسے یہ خصوصیت حاصل ہوئی اور کیا ہی مقدس وہ
خاوند تھا جس کی اہلی محبت کا معیار بھی تقدس وطہارت کے سوا کچھ نہیں تھا !!
اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح خاص خدائی تجویز کے ماتحت وقوع میں آیا تھا!
چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے نکاح سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک
فرشتہ آپ کے سامنے ایک ریشمی کپڑا پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے آپ اسے کھولتے ہیں
تو اس میں حضرت عائشہ کی تصویر پاتے ہیں مگر آپ نے اس خواب کا کسی سے ذکر نہیں فرمایا اور سمجھ لیا کہ
اگر اس خواب نے اپنی ظاہری صورت میں پورا ہونا ہے تو خدا خود اس کا سامان کر دے گا ! چنانچہ بالآ خر خولہ
بنت حکیم کی تحریک سے یہ رشتہ قائم ہو گیا.احادیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ آخری ایام میں حضرت سودہ
بنت زمعہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دیدی تھی اور اس طرح حضرت عائشہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت سے مستفیض ہونے کا دوہرا موقع میسر آ گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس زمانہ میں شریعت کا
نزول ہور ہا تھا اور ہر امر میں جدید دستور العمل کی بنیاد پڑ رہی تھی ، اس لیے جب حضرت سودہ بوڑھی ہو گئیں اور
پورے طور پر حقوق زوجیت کی ادائیگی کے قابل نہ رہیں تو انہیں اپنی جگہ یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں انہیں علیحدہ کر دیں اس لیے انہوں نے خود ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ا : ابن سعد جلد ۸ صفحه ۴۶ ے : بخاری باب مناقب ابی بکر ے ، بخاری باب فضل عائشہ
۵ : بخاری کتاب النکاح
Page 504
۴۸۹
خدمت میں یہ عرض کر کے کہ یا رسول
اللہ مجھے اب باری کی ضرورت نہیں ہے اپنی باری حضرت عائشہ کو
دے دی.ان کا یہ خیال تو سراسر غلط اور محض وہم پر مبنی تھا، لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت عائشہ کی تعلیم وتربیت کا خاص خیال تھا اور وہ اپنی عمر اور حالات کے لحاظ سے اس قابل تھیں کہ
ان پر خاص توجہ صرف کی جاوے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باری کے متعلق سودہ کی تجویز
منظور فرمالی مگر اس کے بعد بھی آپ حضرت سودہ کے پاس باقاعدہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور دوسری
بیویوں کی طرح ان کی دلداری اور آرام کا خیال رکھتے تھے.حضرت عائشہ کے خواندہ ہونے کے متعلق اختلاف ہے مگر بخاری کی ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ
ان کے پاس ایک نسخہ قرآن شریف کا لکھا ہوا موجود تھا.جس پر سے انہوں نے ایک عراقی مسلمان کو
بعض آیات خود املا کرائی تھیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کم از کم خواندہ ضرور تھیں اور اغلب ہے کہ
انہوں نے اپنے رخصتانہ کے بعد ہی لکھنا سیکھا تھا، لیکن جیسا کہ بعض مؤرخین نے تصریح کی ہے وہ غالباً
لکھنا نہیں جانتی تھیں..حضرت عائشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم و بیش اڑتالیس سال
زندہ رہیں اور ۵۸ ہجری کے ماہ رمضان میں اپنے محبوب حقیقی سے جاملیں.اس وقت ان کی عمر قریباً
اڑسٹھ سال
کی تھی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے رخصتانہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے حرم میں تعدد ازدواج کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس موقع
تعد دازدواج اور اس کی حکمتیں پر اس مسئلہ کے متعلق ایک مختصر سا نوٹ درج کرنا نا مناسب
نہ ہوگا لیکن پیشتر اس کے کہ تعد دازدواج کے متعلق کچھ بیان کیا جاوے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ
اغراض بیان کر دی جائیں جو اسلامی شریعت میں نکاح کی مقرر کی گئی ہیں.کیونکہ منجملہ اور اغراض کے ان
اغراض کے توسیعی مصالح پر ہی تعدد ازدواج کا ایک حد تک دار و مدار ہے.سو جاننا چاہئے کہ قرآن شریف
سے نکاح کی اغراض چار معلوم ہوتی ہیں.اول انسان کا بعض جسمانی اور اخلاقی اور روحانی بیماریوں اور
ان کے بدنتائج سے محفوظ ہو جانا.اس صورت کو عربی میں احصان کہتے ہیں جس کے لفظی معنے کسی قلعہ
کے اندر محفوظ ہو جانے کے ہیں.دوم بقائے نسل سوم حصول رفیق حیات اور سکینت قلب، چهارم محبت
ل : ترندی وابوداؤد بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۲۹
: بلاذری باب امر الخط
: باب تالیف القرآن
Page 505
۴۹۰
اور رحمت کے تعلقات کی توسیع ، چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے:
وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ
اور اے مسلمانو! جائز کی جاتی ہیں تمہارے لیے تمام عورتیں سوائے ان عورتوں کے جن
کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ کہ تم ان کے مہر مقرر کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو مگر تمہارے نکاح کی
غرض یہ ہونی چاہئے کہ تم بیماریوں اور بدیوں سے محفوظ ہو جا ؤ اور یہ غرض نہیں ہونی چاہئے کہ تم
شہوت کے طریق پر عیش و عشرت میں پڑو.“
اس آیت میں احصان والی غرض بیان کی گئی ہے یعنی (الف ) یہ کہ نکاح کے ذریعہ انسان بعض
ان خاص قسم کی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچ جاوے جو تجرد کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اور
(ب) یہ کہ وہ بعض روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے محفوظ ہو جاوے، لیکن ناپاک خیالات اور ناپاک
تعلقات میں مبتلا نہ ہو.اسی غرض وغایت کو ایک دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے:-
هُنَّ لِبَاسٌ نَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ :
”اے مسلمان مرد و یا درکھو کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کا لباس ہو.“
یعنی تم ایک دوسرے کو بدیوں اور بیماریوں سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہو جیسا کہ لباس انسان کے لیے
سردی اور گرمی کی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے.اس آیت میں چونکہ عورتوں کو بھی شامل کرنا تھا اس
لیے طریق بیان زیادہ لطیف کر دیا گیا ہے.نیز اس آیت میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے
کے لیے پردہ پوشی کا بھی ذریعہ ہیں جیسا کہ لباس بھی پردہ پوشی کا ذریعہ ہوتا ہے.پھر فرماتا ہے:
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
یعنی ”اے مسلمانو! تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں جن سے تمہاری آئندہ نسل کی فصل
نے پیدا ہونا ہے.پس اب تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں کے ساتھ معاملہ کرو
اور جس قسم کی فصل اپنے لیے پیدا کرنا چاہو پیدا کرلو.“
اس آیت میں بقائے نسل کی غرض بیان کی گئی ہے یعنی یہ کہ انسانی نسل کا سلسلہ قائم رہے اور ساتھ ہی
خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف پیرا یہ میں یہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ جب بیویوں کے ذریعہ آئندہ نسل کا وجود
: سورۃ نساء : ۲۵
: بقره : ۱۸۸
۳ : بقره : ۲۲۴
Page 506
۴۹۱
قائم ہونا ہے تو پھر انسان کو چاہئے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ایسا طریق اختیار کرے کہ جس
کے نتیجہ میں آئندہ نسل خراب نہ ہو بلکہ بہتر سے بہتر نسل پیدا ہو.پھر فرماتا ہے:
وَرَحْمَةٌ
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً
یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس میں سے ہی تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں تا کہ تم ان کے
تعلق میں سکینت قلب حاصل کرو اور پھر اس تعلق کو خدا نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا
ذریعہ بنایا ہے.“
اس آیت میں نکاح کی تیسری اور چوتھی اغراض بیان کی گئی ہیں.یعنی یہ کہ خاوند کو بیوی میں اور بیوی
کو خاوند میں رفیق حیات میسر آجاوے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے تعلق میں
تسکین قلب پائیں اور
دوسرے یہ کہ نکاح کے ذریعہ سے خاوند اور بیوی کے متعلقین کے درمیان رشتہ وداد و اتحاد قائم ہو جاوے
اور نسلی رشتہ داری کے تعلق کے علاوہ رحمی تعلق کے ذریعہ بھی مختلف خاندانوں اور مختلف قوموں کے درمیان
محبت اور رحمت کی زنجیر سے منسلک ہو جانے کے موقعے میسر رہیں.الغرض اسلامی شریعت میں نکاح کی چار اغراض بیان کی گئی ہیں.اوّل احصان یعنی بعض جسمانی اور
روحانی بیماریوں اور ان کے نتائج سے محفوظ ہو جانا.دوم بقاء نسل سوم رفاقت حیات اور تسکین قلب،
چہارم مختلف خاندانوں یا مختلف قوموں کا آپس میں محبت اور رحمت کے رشتہ کے ذریعہ سے مل جانا اور
اگر غور کیا جاوے تو یہ ساری اغراض نہ صرف بالکل جائز اور مناسب ہیں بلکہ نہایت درجہ پاکیزہ اور
فطرت انسانی اور ضروریات بنی نوع انسان کے عین مطابق ہیں اور ان سے خاوند بیوی کے تعلق کو ایک
بہترین بنیاد پر قائم کر دیا گیا ہے اور اس تعلق سے بہترین ثمرہ پیدا کرنے کی صورت نکالی گئی ہے اور ان
اغراض کے مقابلہ میں جس غرض کو قرآن شریف نے نام لے کرنا جائز قرار دیا اور اس سے مسلمانوں کو روکا
ہے وہ تعیش اور شہوت رانی کی غرض ہے.اب ہم وہ اغراض بیان کرتے ہیں جو تعدد ازدواج کی اجازت میں اسلام نے مد نظر رکھی ہیں.سواسلامی شریعت کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اغراض دو قسم کی ہیں.اوّل وہی عام اغراض جو نکاح
ل : سورة روم :
۲۲:
Page 507
۴۹۲
میں اسلام کے مد نظر ہیں اور جو اوپر بیان کی جاچکی ہیں.دوم وہ خاص اغراض جو مخصوص طور پر تعدّد
ازدواج کے ساتھ وابستہ ہیں.مقدم الذکر اغراض کو تعدّ دازدواج کے معاملہ میں اس لیے بحال رکھا گیا
ہے کہ بعض اوقات ایک بیوی سے نکاح کی غرض پورے طور پر حاصل نہیں ہوتی اور اس لیے اسی غرض کے
ماتحت دوسری بیوی کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے.مثلاً نکاح کی ایک غرض احصان ہے یعنی یہ کہ اس ذریعہ
سے انسان بعض بیماریوں اور بدیوں اور بدکاریوں سے بچ جاوے لیکن ہوسکتا ہے کہ انسان کے حالات
ایسے ہوں کہ وہ ایک ہی عورت کے تعلق سے جس پر حیض اور حمل اور وضع حمل اور رضاعت اور پھر مختلف قسم
کی بیماریوں وغیرہ کی حالتیں آتی رہتی ہیں اپنے تقویٰ اور طہارت کو قائم نہ رکھ سکتا ہو.اور اگر وہ غیر معمولی
کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو عملی بدی سے بچائے بھی رکھے تو کم از کم اس کے خیالات میں ناپاکی کا عنصر
غالب رہتا ہوا ور یا اس طرح رکے رہنے سے اسے کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسے
شخص کا صحیح علاج سوائے تعد دازدواج کے اور کوئی نہیں.یعنی وہی غرض جو ایک نکاح کی محرک تھی اس
صورت میں اس کے لیے دوسرے نکاح کی محرک ہو جائے گی.اسی طرح نکاح کی ایک غرض بقائے نسل
ہے، لیکن اگر کسی شخص کے ہاں ایک بیوی سے کوئی اولاد نہ ہو یا نرینہ اولا دنہ ہوتو یہی غرض دوسرے نکاح کی
جائز بنیاد بن جائے گی.اسی طرح نکاح کی ایک غرض رفاقت حیات اور تسکین قلب ہے، لیکن اگر کسی کی
بیوی دائم المریض ہو اور اس کا مرض اس حالت کو پہنچا ہوا ہو کہ وہ بالکل صاحب فراش رہتی ہو یا وہ مجنون ہو
جاوے تو اس صورت میں ایسے شخص کو رفاقت حیات اور تسکین قلب کی غرض کو پورا کرنے کے لیے دوسری
بیوی کی ضرورت ہوگی.اسی طرح نکاح کی ایک غرض مختلف خاندانوں کا آپس میں ملنا اور ایک دوسرے
کے لیے محبت ورحمت کے موقعے پیدا کرنا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے ابتداء کسی ایسے خاندان
میں شادی کی ہو جہاں اس کے لیے اس رشتہ محبت کا قائم ہونا ضروری تھا ، مگر اس کے بعد اس کے لئے اس
سے بھی زیادہ ضروری اور اہم موقعے پیش آجائیں جہاں اس کا تعلق قائم ہونا خاندانی یا قومی یا ملکی یا سیاسی یا
دینی مصالح کے ماتحت نہایت ضروری اور پسندیدہ ہو تو اس صورت میں اس کے لیے تعد دازدواج پر عمل
کرنا ضروری ہو جائے گا.الغرض وہ ساری اغراض جو اسلام نے نکاح کے متعلق بیان کی ہیں وہی خاص
حالات میں تعد دازدواج کی بنیاد بھی بن جاتی ہیں اور مندرجہ بالاصورتیں مثال کے طور پر بیان کی گئی ہیں ؟
ور نہ اور بعض صورتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ جب نکاح کی غرض ایک بیوی سے پورے طور پر یا احسن صورت
میں حاصل نہیں ہوتی اور دوسری بیوی کی جائز طور پر ضرورت پیش آجاتی ہے، لیکن ان اغراض کے علاوہ
Page 508
۴۹۳
اسلام نے تعد دازدواج کی بعض خاص وجوہات بھی بیان کی ہیں وہ تین ہیں.اول حفاظت یتامی ، دوم
انتظام بیوگان ، سوم تکثیر نسل.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
اور ” اے مسلمانو! ( ان جنگوں میں جو تمہیں در پیش ہیں لاز ما یتامی کی کثرت ہوگی اور
تمہیں ان بیتامی کی حفاظت کے لیے تعدد ازدواج کی ضرورت پیش آئیگی.پس ) اگر تمہیں یہ
اندیشہ ہو کہ (ایک بیوی تک محدود رہتے ہوئے ) تم بیتامی کی حفاظت اور ان کے حقوق کی
خاطر خواہ ادائیگی سے قاصر رہو گے تو پھر اپنی پسند کے مطابق زیادہ عورتوں سے شادیاں کرو.دو دو کے ساتھ ، تین تین کے ساتھ اور چار چار کے ساتھ ( مگر اس سے زیادہ نہیں کیونکہ خدا کی
نظر میں یہ حد تمہاری استثنائی ضروریات کے لیے کافی ہے، لیکن اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اپنی
مالی یا جسمانی یا انتظامی کمزوری کی وجہ سے یا طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے ) تم ایک سے زیادہ
عورتوں کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں لازماً ایک ہی بیوی
سے شادی کرنی چاہئے.“
اس آیت کریمہ میں تعد دازدواج کے حکم کو یتامیٰ کے ذکر کے ساتھ ملا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا
گیا ہے کہ دراصل یتامی کی کثرت بھی تعدد ازدواج کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے اور چونکہ
یتامی کی کثرت ایک طرف تو بیو گان کی کثرت کو چاہتی ہے اور دوسری طرف وہ آئندہ کے لیے نسل کی قلت
کا اندیشہ پیدا کرتی ہے اور ویسے بھی یہ تینوں حالتیں جنگ کا لازمی نتیجہ ہیں.اس لیے گویا اس آیت میں ہی
خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف پیرایہ میں تعدد ازدواج کی ساری زائد اغراض کو جمع کر دیا ہے.یعنی حفاظت
یتامی ، انتظام بیوگان اور علاج قلت نسل اور پھر مزید تشریح و توضیح کے لیے ان کا علیحدہ علیحدہ ذکر بھی کیا
ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.وَاَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
یعنی ”اے مسلمانو! ( اب جب ہم نے تمہارے لیے تعد دازدواج کا استثنائی علاج تجویز
کر دیا ہے تو ) اب تمہیں ایسا انتظام کرنا چاہئے کہ حتی الوسع کوئی غیر شادی شدہ عورت خواہ وہ
: سورۃ نساء : ۴
: سورة نور : ۳۳
Page 509
۴۹۴
کنواری ہو یا بیوہ ہو بغیر شادی کے نہ رہے.“
اس آیت میں غیر شادی شدہ عورتوں خصوصاً بیوگان کی شادی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.پھر حدیث میں آتا ہے:
عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجُوا
الْوَدُوْدَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْامَمَ
یعنی « معقل بن سیار روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب
سے فرماتے تھے کہ تمہیں چاہئے کہ محبت کرنے والی زیادہ بچے دینے والی عورتوں کے ساتھ
شادیاں کیا کرو ، تا کہ تمہاری تعداد ترقی کرے اور میں قیامت کے دن اپنی امت کی زیادتی پر
فخر کر سکوں.“
اس حدیث میں تکثیر نسل والی غرض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.اس طرح یہ کل سات اغراض ہوتی ہیں جو اسلام نے تعدد ازدواج کے متعلق بیان کی ہیں.یعنی
جسمانی اور روحانی بیماریوں سے حفاظت ، بقائے نسل ، رفاقت قلب محبت و رحمت کے تعلقات کی توسیع ،
انتظام یتامی ، انتظام بیوگان اور ترقی نسل.لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اغراض کو حاصل کس طرح
کیا جاوے یعنی کس اصل کے ماتحت بیوی کا انتخاب کیا جاوے کہ یہ اغراض احسن صورت میں حاصل
ہوسکیں.سواس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعِ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِ يُنهَا فَاظُفِرُ بِذَاتِ الدِّيْنِ
تَرِبَتْ يَدَاكَ
یعنی ” نکاح میں عورت کا انتخاب چار قسم کے خیالات کے ماتحت کیا جاتا ہے.بعض لوگ
عورت کی مالی حالت کی بنا پر بیوی کا انتخاب کرتے ہیں بعض کو حسب ونسب کا خیال ہوتا ہے.بعض خوبصورتی اور حسن دیکھتے ہیں اور بعض لوگ عورت کی اخلاقی اور دینی حالت کو مدنظر رکھتے
ہیں لیکن اے مسلمانو! تمہیں چاہئے کہ تم ہمیشہ دینی پہلو کو ترجیح دیا کرو.یہی تمہاری کامیابی کا
طریق اور یہی دین و دنیا کی خرابی سے بچنے کا طریق ہے.“
اس حدیث میں نکاح کی اغراض کے حصول کے لیے بیوی کے انتخاب کا اصول بتایا گیا ہے اور وہ یہ
ل : ابوداؤ دو نسائی بحوالہ مشکوۃ کتاب النکاح
: بخاری کتاب النکاح
Page 510
۴۹۵
ہے کہ دینی پہلو کو ترجیح دی جاوے اور دین سے صرف عورت کی ذاتی دینی یا اخلاقی حالت مراد نہیں ہے
اور نہ دین کا لفظ عربی زبان میں محض مذہب اور عقیدہ کے معنوں میں آتا ہے بلکہ جیسا کہ عربی کی مشہور
لغت اقرب الموارد میں تشریح کی گئی ہے دین کا لفظ عربی زبان میں مندرجہ ذیل معانی کے اظہار کے لیے
استعمال ہوتا ہے.اول اخلاق و عادات، دوم روحانی پاکیزگی اور طہارت، سوم مذہب، چهارم قوم وملت ،
پنجم سیاست وحکومت.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ عورت کے انتخاب میں دینی
پہلو کو ترجیح دی جاوے اس میں جہاں یہ مراد ہے کہ بیوی ایسی ہونی چاہئے جو ذاتی طور پر اخلاق و
عادات اور تقویٰ وطہارت اور مذہب و عقیدہ میں اچھی ہوتا کہ خاوند اور بیوی کے تعلقات بھی اچھے رہیں
اور آئندہ اولاد پر بھی اچھا اثر پڑے، وہاں یہ بھی مراد ہے کہ بیوی کے انتخاب میں وہ عام دینی پہلو بھی جو
مصالح مذہب اور مصالح قوم وملت اور مصالح سیاست و حکومت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اپنے اپنے
موقع پر مد نظر رہنے چاہئیں اور اگر اس جگہ کسی کو یہ شبہ گذرے کہ گولغوی طور پر یہ سب معانی درست ہوں
مگر یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ میں ایک ہی وقت میں اتنے معانی مراد ہوں.تو اس کا
جواب یہ ہے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مُقنن نبی تھے.آپ کا کلام قانونی کلام کا رنگ رکھتا
تھا جو ہمیشہ جامع المعانی اور وسیع المفہوم ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ میں کئی کئی پہلو مد نظر ہوتے
ہیں اور اسی روشنی میں ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معنے کرنے چاہئیں اور بہر حال جب
لغوی طور پر یہ معانی درست ہیں تو کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے.خلاصہ کلام یہ کہ اسلام نے نکاح کی اغراض چار اور تعدد ازدواج کی اغراض سات بیان کی ہیں اور
ان اغراض کے بہترین حصول کے لیے بیوی کے انتخاب کے متعلق یہ ہدایت دی ہے کہ اس میں عورت کی
ذاتی خوبی کے علاوہ مصالح مذہب اور مصالح قوم وملت اور مصالح سیاست و حکومت کو ترجیح دینی چاہیئے.اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نکاح کے معاملہ میں اور خوبیوں کو نہ دیکھا جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو عورت کی دوسری خوبیوں کے مد نظر رکھنے
کی بھی اجازت دی ہے بلکہ بعض اوقات خود اس کی تحریک فرمائی ہے کہ دوسری باتوں کو بھی دیکھ لیا کرو.چنانچہ با وجود پردہ کے احکام کے آپ یہ تحریک فرماتے تھے کہ نکاح سے پہلے مرد کو چاہئے کہ عورت کو خود
دیکھ لے یا تا کہ بعد میں شکل وصورت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کی طبیعت میں کسی قسم کا تکدر نہ پیدا
1 : ترمذی ابواب النکاح
Page 511
۴۹۶
ہو.اسی طرح مناسب حد تک مالی حالت کے مدنظر رکھنے کی بھی تحریک کی گئی ہے.اسی طرح ایک حد تک
عمر اور طبیعت کی مناسبت کو بھی ملحوظ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے.اور یہی اصول دوسرے حالات میں
چسپاں ہوتا ہے مگر جس بات کی اسلام ہدایت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ان باتوں کو دینی پہلو کے مقابلہ میں
ترجیح نہیں دینی چاہئے کیونکہ اگر دینی پہلو کی خوبیاں موجود نہ ہوں تو محض یہ خوبیاں حقیقی اور دائمی خوشی
کی بنیاد نہیں بن سکتیں بلکہ بعض صورتوں میں مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں.اب ایک طرف تعد دازدواج کی اغراض اور دوسری طرف اس اصول کو جو بیویوں کے انتخاب کے
لیے اسلام نے تجویز کیا ہے، مدنظر رکھا جاوے تو ہر عقمند سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی بابرکت انتظام ہے
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں قائم کیا ہے اور اس میں بنی نوع انسان کے
بڑے سے بڑے حصہ کی بڑی سے بڑی بھلائی مد نظر ہے.دراصل جن لوگوں نے تعدد ازدواج کے
خلاف رائے ظاہر کی ہے انہوں نے اپنی نظر کو بہت ہی محدود رکھا ہے اور خاوند و بیوی کے جذباتی تعلقات
کے سوا کسی اور بات کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھی اور نہ ان لوگوں نے کبھی ٹھنڈے دل سے نکاح کی اغراض
اور بنی نوع انسان کی ضروریات کے متعلق غور کیا ہے، ورنہ یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی فہمیدہ شخص اس کی
خوبیوں سے انکار کی گنجائش پاتا.پھر یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ تعدد ازدواج کا انتظام اسلام میں قاعدہ کے
طور پر نہیں ہے بلکہ یہ ایک استثناء ہے جو نکاح کی جائز اغراض کے حصول اور نسل انسانی کی جائز ضروریات
کے پورا کرنے کے لیے خاص خاص قسم کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جاری کی گئی ہے.پس اس کے
متعلق رائے لگاتے ہوئے اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ کیا دنیا میں انسان کو ایسے حالات پیش نہیں آسکتے
کہ جن کے ماتحت تعدّ دازدواج ایک ضروری علاج قرار پاتا ہے اور انسان کی ذات یا اس کے خاندان یا
اس کی قوم یا اس کے ملک کے مفاد اس بات کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسری بیوی سے شادی
کرے.مجھے شہنشاہ نپولین کی زندگی کا وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ جب اس نے اپنے ملکی مفاد کے ماتحت حصول
اولاد کی غرض سے دوسری بیوی کی ضرورت محسوس کی مگر یہ ضرورت کس طرح پوری کی گئی ؟ اس کے تصور
سے میرے بدن پر ایک لرزہ آ جاتا ہے.شہنشاہ کی ملکہ جوزفین کی طلاق کا واقعہ تاریخ کے تاریک ترین
واقعات میں سے ہے اور اس کی تہہ میں یہی جھوٹا جذباتی خیال ہے کہ انسان کو کسی صورت میں بھی ایک
مسلم کتاب الرضاع باب المطلقه ثلاثا لا نفقة لها
مسلم کتاب الرضاع باب استحباب نکاح البکر و بخاری کتاب النکاح باب الشیبات
Page 512
۴۹۷
سے زیادہ بیوی نہیں کرنی چاہئے.افسوس! اس جھوٹے جذباتی خیال نے کئی کمزور لوگوں کے تقویٰ پر ڈا کہ
ڈالا.کئی خاندانوں کو بے نسل کر کے دنیا سے مٹا دیا.کئی گھروں کی خوشیوں کو تباہ کیا.کئی گھرانوں اور کئی
قوموں اور کئی ملکوں کے اتحاد کی امیدوں پر پانی پھیر دیا.کئی یتیموں کو آوارہ کیا.کئی بیوگان کو کسمپرسی کی
حالت میں چھوڑا.کئی قوموں کی نسل کو تنزل کے رستے پر ڈال کر ان کی تباہی کا بیج بویا اور یہ سب کچھ صرف
اس لیے ہوا کہ عورت ہر صورت میں اپنے خاوند کی توجہ کی اکیلی مالک بنی رہے ! مگر یہ ایک عجیب قربانی ہے
کہ بڑی چیز کو چھوٹی چیز پر قربان کیا جاتا ہے؛ حالانکہ حق یہ تھا کہ اخلاقی فوائد پر مادی فوائد قربان کئے
جاتے.دینی منافع پر دنیاوی منافع قربان کئے جاتے.خاندانی مصالح پر ذاتی مصالح قربان کئے جاتے.قومی مفاد پر انفرادی مفاد قربان کیے جاتے اور در حقیقت تعد دازدواج کا تو انتظام ہی ایک مجسم قربانی کا
انتظام ہے اور اس میں خاوند اور بیوی دونوں کی ذاتی اور جسمانی قربانی ذریعہ اخلاق اور دینی اور خاندانی
اور قومی اور ملکی مصالح کے لیے راستہ کھولا گیا ہے.خلاصہ کلام یہ کہ اسلام میں تعد دازدواج کا انتظام ایک
استثنائی انتظام ہے جو انسانوں کی خاص ضروریات کو مد نظر رکھ کر جاری کیا گیا ہے اور یہ ایک قربانی ہے جو
مرد اور عورت دونوں کو اپنے اخلاق اور دین اور خاندان اور قوم اور ملک کے لیے خاص حالات میں کرنی
پڑتی ہے اور اسلام ہر شخص سے امید رکھتا ہے کہ وہ اس قسم کے حالات کے پیدا ہونے پر جو تعدد ازدواج
کے لیے ضروری ہیں اپنی خواہش اور اپنے جسمانی آرام کو زیادہ بڑے مفاد کے لیے قربانی کر دینے میں
تامل نہیں کرے گا اور موقع پیش آنے پر یہ ثابت کر دے گا کہ اس کی زندگی صرف اس کی ذات یا اس کے
گھر تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی وسیع انسانیت کا ایک فرد ہے جس کی خاطر اسے اپنے شخصی مفاد کے
قربان کرنے میں دریغ نہیں کرنا چاہئے.پھر یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ تعد دازدواج کی جائز ضرورت کے پیدا ہونے پر بھی اسلام نے تعدّ دازدواج
کو لازمی نہیں قرار دیا بلکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اسے اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اگر انسان
عدل کرنے کے قابل ہو تو تب تعدد ازدواج پر عمل کرے ورنہ بہر حال صرف ایک بیوی پر ہی اکتفا کرے
اور عدل سے اس جگہ صرف بیویوں کے درمیان عدل کرنا مراد نہیں بلکہ ان کے ہر قسم کے حقوق کا ادا کرنا
مراد ہے جو تعدد ازدواج کی صورت میں انسان پر عائد ہوتے ہیں.پس تعد داز دواج کی دو شرطیں
ہوئیں.اوّل ان جائز اغراض میں سے کسی غرض کا پیدا ہو جانا جو اسلام نے اس کے لیے مقرر کی ہیں.دوم انسان کا عدل کر سکنے کے قابل ہونا اور ان دونوں شرطوں کے پورا ہونے کے بغیر تعد دازدواج پر عمل
ا
Page 513
۴۹۸
کرنے والا شخص اپنے وقت ، اپنی توجہ ، اپنے مال ، اپنے ظاہری سلوک غرضیکہ دل کی محبت کے سوا جس پر
انسان کو اختیار نہیں ہوتا باقی سب چیزوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بلاکم وکاست ایک سا معاملہ کرے.اور غور کیا جاوے تو یہ پابندی خود ایک عظیم الشان قربانی ہے جو خاوند کو کرنی پڑتی ہے.خصوصاً ایسی حالت
میں کہ اسے اپنی بیویوں میں سے ان کے ذاتی حالات اور ذاتی قابلیت کے فرق کی وجہ سے کسی سے زیادہ
محبت ہوتی ہے اور کسی سے کم مگر پھر بھی وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنی ہر چیز کو تر از و کی طرح تول کر اپنی بیویوں
میں برابر برابر تقسیم کرے اور یہ قربانی صرف خاوند ہی کی قربانی نہیں بلکہ اس قربانی میں اس کی بیویاں بھی
برابر کی شریک ہوتی ہیں.ان حالات میں ہر عقلمند شخص سمجھ سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلام نے تعدد ازدواج
کے معاملہ میں تعیش کے خیال تک سے منع فرمایا ہے بلکہ اس نے اس کے لیے عملی طور پر شرطیں بھی ایسی
لگادی ہیں کہ کوئی شخص ان شرطوں پر کار بند ہوتا ہوا عیش وعشرت میں پڑ ہی نہیں سکتا.اس موقع پر یہ ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں بلکہ دنیا کی کسی قوم میں بھی
تعدد ازدواج کی کوئی حد بندی نہیں تھی اور ہر شخص جتنی بیویاں بھی چاہتا تھا رکھ سکتا تھا.مگر اسلام نے علاوہ
دوسری شرائط عائد کرنے کے تعداد کے لحاظ سے بھی اسے زیادہ سے زیادہ چار تک محدود کر دیا؛ چنانچہ
تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جن نو مسلموں کی چار سے زیادہ بیویاں تھیں انہیں یہ حکم دیا جا تا تھا کہ وہ باقیوں کو
طلاق دیدیں.مثلا غیلان بن سلمہ تھی جب مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں.جن میں سے چھ کو
حکماً طلاق دلوا دی گئی.اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں کون سی اغراض مد نظر تھیں کیونکہ
ہمارا اصل مضمون یہی ہے.سو جاننا چاہئے کہ عام اغراض تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں وہی
تھیں جو اسلام نے عام طور پر نکاح اور تعدد ازدواج کی بیان کی ہیں اور جن کا ذکر اوپر گذر چکا ہے اور
ان اغراض میں سے خصوصیت کے ساتھ آپ کے مد نظر بقائے نسل محبت اور رحمت کے تعلقات کی توسیع
اور انتظام یتامی و بیوگان کی غرضیں تھیں اور محبت اور رحمت کے تعلقات کی توسیع کی غرض کے ماتحت آپ
کے پیش نظر ایسی عورتیں تھیں جو مصالح قوم وملت اور مصالح سیاست وحکومت کے لحاظ سے زیادہ مناسب
تھیں لیکن ان عام اغراض کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص حالات کے ماتحت آپ کی
شادیوں کی بعض خاص وجوہات بھی تھیں اور یہ اغراض دو تھیں.اوّل آپ کے ذاتی نمونہ سے بعض جاہلانہ
: مشكلوة كتاب القسم
: ترندی ابواب النکاح
Page 514
۴۹۹
رسوم اور غلط عقائد کی عملی تر دید.دوم بعض مناسب عورتوں کو آپ کی تربیت میں رکھ کر ان کے ذریعہ
اسلامی شریعت کے اس حصہ کا استحکام جو مستورات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مسلمان عورتوں کی تعلیم و
تربیت ؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے:
فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرَازَ وَجُنُكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٍ
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا LO
یعنی ”اے رسول! جب تیرے مُنہ بنائے بیٹے زید بن حارثہ نے اپنی بیوی زینب کو طلاق
دیدی تو ہم نے اس کی شادی کی تجویز خود تیرے ساتھ کر دی تا کہ اس ذریعہ سے یہ جاہلانہ رسم
مٹ جاوے کہ منہ بلایا بیٹا اصل بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی مطلقہ بیوی یا بیوہ بیٹا
بنانے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہوتی اور آئندہ کے لیے مومنوں کے دلوں میں اس امر
کے متعلق کوئی دیدہ یا خلش باقی نہ رہے.“
اس آیت میں پہلی غرض بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ کے ذریعہ
سے بعض ان جاہلانہ رسوم کا استیصال کیا جاوے جو عربوں کی طبیعت میں اس قدر راسخ ہو چکی تھیں کہ ان کا
حقیقی استیصال بغیر اس کے ناممکن تھا کہ آپ اس معاملہ میں خود ایک عملی نمونہ قائم کریں ؛ چنانچہ متبنی بنانے
کی رسم عرب میں بہت راسخ اور رائج تھی اور اس معاملہ میں الہی حکم نازل ہونے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو تینی بنایا ہوا تھا ، اس لیے جب یہ حکم نازل ہوا کہ کسی شخص کو
محض منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ اصل بیٹا نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آگیا کہ زید بن حارثہ
نے اپنی بیوی زینب بنت جحش کو طلاق دیدی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی حکم کے ماتحت زینب
کے ساتھ خود شادی فرمائی اور اس طرح اس جاہلانہ رسم کا استیصال کیا جو آپ کے عملی نمونہ کے بغیر پوری
طرح مٹنی محال تھی.علاوہ ازیں آپ نے زینب کے ساتھ شادی کر کے اس بات میں بھی عملی نمونہ قائم فرمایا
کہ کسی طلاق شدہ عورت کے ساتھ شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے.پھر فرماتا ہے:
يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمَيَّحْكُنَ وَأُسَرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا وَإِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ
سورۃ احزاب : ۳۸
Page 515
۵۰۰
الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا..يُنسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ
كَاحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ وَأَقِمْنَ الصَّلوةَ وَاتِينَ الزَّكَوةَ وَاَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُظْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ
مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ أَيْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفَا خَبِيرًا :
یعنی اے نبی ! تم اپنی بیویوں سے کہدو کہ اگر تمہیں یہ خواہش ہے کہ دنیا کی زندگی کا
ساز وسامان تمہیں مل جاوے تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دیئے دیتا ہوں ، مگر اس صورت
میں تم میری بیویاں نہیں رہ سکتیں بلکہ پھر میں احسان و مروت کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں
گا.لیکن اگر تم خدا اور اس کے رسول کی خواہش رکھتی ہو اور آخرت کا اجر چاہتی ہو تو سن لو کہ تم
میں سے ان نیکو کاروں کے لیے جو خدا کے منشا کو پورا کریں خدا نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے.اے نبی کی بیویو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو.اگر تم تقویٰ اختیار کرو اور نماز کو اس
کی اصلی صورت میں قائم کرو اور زکوۃ دو اور خدا اور اس کے رسول کی پوری پوری اطاعت کرو
کیونکہ خدا نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے چنا ہے ) اے نبی کے اہل بیت ! اللہ تعالیٰ چاہتا
ہے کہ تم سے ہر قسم کی کمزوریوں اور نقصوں کو دور کر کے تمہیں خوب اچھی طرح پاک وصاف کر
دے تاکہ تم ان آیات الہی اور ان حکمت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ جو نبی کے ذریعہ سے
تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں اور خدا تعالیٰ تمہارے ذریعہ سے یہ کام اس لیے لینا چاہتا
ہے کہ وہ اگر بوجہ لطیف ہونے کے خود لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور مخفی ہے تو بوجہ خبیر ہونے
کے وہ لوگوں کی ضروریات سے آگاہ بھی ہے.پس ضروری ہے کہ وہ ہدایت خلق کا کام انسانوں
کے واسطے سے سرانجام دے.اس آیت کریمہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کی مخصوص غرض میں سے دوسری
اور بڑی غرض بتائی گئی ہے یعنی یہ کہ آپ کے ساتھ مناسب مستورات کو بطور بیویوں کے رکھ کر انہیں
مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تیار کیا جاوے.یہ وہ خاص الخاص غرض ہے جس کے ماتحت آپ
کی شادیاں وقوع میں آئیں اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی غرض ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ
مخصوص تھی اور اسی لیے عام مسلمانوں کے لیے جو حد بندی تعدد ازدواج کی مقرر کی گئی ہے اس سے آپ
۳۵ ، ۳۴ ، ۳۳ :
: سورۃ احزاب : ۲۹ ، ۳۰
: سورۃ احزاب :
Page 516
۵۰۱
مستغنی تھے.دراصل چونکہ آپ ایک شرعی نبی تھے اور آپ کے ذریعہ سے دنیا میں ایک نئے شرعی قانون اور
نئے تہذیب و تمدن کی بنیاد پڑنی تھی اس لیے صرف اس قدر کافی نہیں تھا کہ آپ کے ذریعہ نئے احکام کی
اشاعت ہو جاتی بلکہ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ آپ خود اپنی نگرانی میں اس نئی شریعت کو تفصیلاً جاری
فرماتے اور لوگوں کی زندگیوں کو اس جدید داغ بیل پر عملاً چلا دیتے جو اسلام نے قائم کی تھی.یہ کام ایک
نہایت مشکل اور نازک کام تھا اور گومردوں کے معاملہ میں بھی آپ کے رستے میں بہت سی مشکلات تھیں
لیکن مستورات کے متعلق تو یہ ایک نہایت ہی مشکل کام تھا کیونکہ اول تو بوجہ ان کے عموماً اپنے گھروں میں
رہنے اور اپنے خانگی مشاغل کی مصروفیت کے انہیں آپ کی صحبت سے مستفیض ہونے کے زیادہ موقعے
نہیں تھے.دوسرے اس طبعی حیاء کی وجہ سے جو عورتوں میں ہوتی ہے وہ ان مخصوص مسائل کو جو عورتوں کے
ساتھ تعلق رکھتے ہیں زیادہ آزادی کے ساتھ آپ سے دریافت نہیں کر سکتی تھیں اور اس کے مقابلہ میں
عورتوں میں تعلیم کی نسبتا کمی اور جاہلانہ رسوم کی پابندی نسبتا زیادہ ہوتی ہے.جس کی وجہ سے وہ اپنے مقررہ
طریق میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتیں ان حالات میں عورتوں
کی تعلیم و تربیت کے
متعلق خاص انتظام کی ضرورت تھی اور اس کی بہترین صورت یہی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مناسب
عورتوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں اپنی تربیت میں اس کام کے قابل بنادیں اور پھر آپ کی یہ ازواج
مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام سرانجام دیں؛ چنانچہ یہ تجویز کارگر ہوئی اور مسلمان عورتوں نے
بڑی خوبی کے ساتھ اور نہایت قلیل عرصہ میں اپنی زندگیوں کو جدید شریعت کے مطابق بنالیا.حتی کہ دنیا کی
کسی قوم میں یہ مثال نظر نہیں آتی کہ طبقہ نسواں نے ایسے قلیل عرصہ میں اور اس درجہ تکمیل کے ساتھ ایک
بالکل نئے قانون اور نئے تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا ہو.اس بات کا ایک عملی ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں نفسانی اغراض کے ماتحت نہیں
تھیں بلکہ دینی اغراض کے ماتحت تھیں اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے بعض ایسی عورتوں کے ساتھ
شادی فرمائی جو اتنی عمر کو پہنچ چکی تھیں کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھیں.مثلاً حضرت ام سلمہ
جن سے آپ نے ۴ ہجری میں شادی فرمائی.ان کی عمر شادی کے وقت پیدائش اولا دوغیرہ کی حد سے تجاوز
کر چکی تھی.چنانچہ انہوں نے اس بنا پر عذر بھی کیا مگر چونکہ آپ کی غرض و غایت دینی تھی اور اس غرض کے
لیے وہ بہت مناسب تھیں.اس لیے آپ نے ان
کو باصرار رضامند کر کے ان کے ساتھ شادی فرمالی.اے
ل : نسائی بحوالہ زرقانی جلد ۲ حالات ام سلمہ وا ابن سعد جلد ۸ حالات ام سلمه
Page 517
۵۰۲
الغرض وہ اغراض جن کے ماتحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں وقوع میں آئیں نہایت
مبارک اور پاکیزہ تھیں اور ان میں غالب طور پر فرائض نبوت کی ادائیگی مدنظر تھی اور شادیوں پر ہی موقوف
نہیں بلکہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جاوے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ جو کام
بھی کرتے تھے خواہ وہ بظاہر دنیا کا ہو یا دین کا اس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ آپ کی مقدم اور غالب غرض
فرائض نبوت کی ادائیگی ہوتی تھی اور دنیا کی نعمتوں سے آپ کو کبھی بھی شغف نہیں ہوا اور مندرجہ ذیل
حدیث یقینا آپ کی زندگی کا بہترین نقشہ ہے:
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَامَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ
وَقَدْ أَثَرَ فِي جَسَدِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اَمَرُ تَنَا أَنْ نَبُسُطُ لَكَ
وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ
رَاحَ وَتَرَكَهَا
یعنی ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی اور
کھردری چٹائی پر لیٹ کر سو گئے جب آپ اُٹھے تو اس چٹائی کا نشان آپ کے جسم پر نظر آتا
تھا.اس پر میں نے عرض کیا یا رسول
اللہ آپ پسند فرما ئیں تو ہم آپ کے لیے آرام و آسائش کا
سامان مہیا کر دیں.آپ نے فرمایا ابن مسعود! مجھے دنیا کی نعمتوں سے کیا کام ہے میری اور دنیا
کی مثال تو یہ ہے کہ ایک سوار راستہ پر چلا جاتا ہو اور وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سایہ
کے نیچے دم لینے کے لیے ٹھہر جاوے اور پھر اٹھ کر اپنا راستہ لے لے.“
اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے متمتع ہونا منع ہے کیونکہ اسلام کسی جائز نعمت سے
جائز طور پر متمتع ہونے سے منع نہیں کرتا بلکہ خود قرآن شریف میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ:
رَبَّنَا أُتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً :
یعنی ” اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی نعمتوں سے بھی حصہ دے اور آخرت کی نعمتوں سے
بھی حصہ دے.“
پس حدیث مندرجہ بالا سے صرف مراد یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا اصل مقصد دنیا کی نعمتوں کا
حصول
نہیں سمجھنا چاہئے اور نیز اس حدیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر
ا : مسند احمد و ترندی بحوالہ مشکوة کتاب الرقاق صفحه ۴۴۲
: بقرة : ۲۰۲
Page 518
۵۰۳
دنیا کی نعمتوں سے قطعاً کوئی شغف نہیں تھا اور جہاں تک نعماء دنیا کا تعلق ہے آپ کی زندگی ایک محض
مسافرانہ زندگی تھی.تعدد ازدواج کے متعلق اس نوٹ میں یہ ذکر بھی بے موقع نہ ہوگا کہ تعددازدواج کی اجازت دینے
میں اسلام اکیلا نہیں ہے بلکہ دنیا کے اکثر مذاہب میں تعدد ازدواج کی اجازت دی گئی ہے مثلاً موسوی شریعت
میں اس کی اجازت ہے.یا اور بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء اس پر عملاً کار بند رہے ہیں.یہ ہندوؤں کے
مذہب میں تعدد ازدواج کی اجازت ہے.اور کئی ہندو بزرگ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے رہے ہیں مثلاً
کرشن جی تعدد ازدواج پر عملاً کار بند تھے.اور ہندو راجے مہاراجے تو اب تک تعدد ازدواج پر کار بند
پر
ہیں.اسی طرح حضرت مسیح ناصری کا بھی کوئی قول تعدد ازدواج کے خلاف مروی نہیں ہے اور چونکہ
شریعت موسوی میں اس کی اجازت تھی اور عملاً بھی حضرت مسیح ناصری کے زمانہ میں تعد دازدواج کا رواج
تھا، اس لیے ان کی خاموشی سے یہی نتیجہ نکالا جائیگا کہ وہ اسے جائز سمجھتے تھے.پس اسلام نے اس میں کوئی
جدت نہیں کی ؛ البتہ اسلام نے یہ کیا کہ تعدد ازدواج کی حد بندی کر دی اور اسے ایسے شرائط کے ساتھ
مشروط کر دیا کہ افراد اور اقوام کے استثنائی حالات کے لیے ایک مفید اور بابرکت نظام قائم ہو گیا.اس نوٹ کے خاتمہ پر یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ گو مخالفین کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
شادیوں پر بہت سخت سخت اعتراض کئے گئے ہیں اور ہر شخص نے اپنی فطرت اور اپنے خیالات کے مطابق
آپ کے تعدد ازدواج کے مسئلہ کو دیکھا ہے مگر پھر بھی صداقت کبھی کبھی مخالفین کے قلم و زبان پر بھی غالب
آگئی ہے اور انہیں اگر کلی طور پر نہیں تو کم از کم جزو ا حقیقت کا اعتراف کرنا پڑا ہے؛ چنانچہ مسٹر مار گولیس
بھی جن کی آنکھ عموماً ہر سیدھی بات کو الٹا دیکھنے کی عادی ہے اس معاملہ میں حقیقت کے اعتراف پر مجبور
ہوئے ہیں.وہ اپنی کتاب ”محمد“ میں لکھتے ہیں:
محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی بہت سی شادیاں جو خدیجہ کے بعد وقوع میں آئیں بیشتر
یورپین مصنفین کی نظر میں نفسانی خواہشات پر مبنی قرار دی گئی ہیں لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ زیادہ تر اس جذ بہ پر مبنی نہیں تھیں.محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی بہت سی شادیاں قومی اور
لی: استثناء باب ۲۱ آیت ۱۵ وسلاطین- اباب ۱۱ آیت ۳
: مثلا دیکھو حالات حضرت ابراہیم و حضرت یعقوب و حضرت داؤ داور حضرت سلیمان
و غیر ہم علیہم السلام
: منو
۹
۹
۹
6
6
۱۸۳
۱۴۹
۱۲۲
سری کرشن مصنفہ لالہ لاجپت رائے صفحہ ۹۷ ، ۹۸
Page 519
۵۰۴
سیاسی اغراض کے ماتحت تھیں کیونکہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) یہ چاہتے تھے کہ اپنے خاص خاص
صحابیوں کو شادیوں کے ذریعہ سے اپنی ذات کے ساتھ محبت کے تعلقات میں زیادہ پیوست کر
لیں.ابوبکر و عمر کی لڑکیوں کی شادیاں یقیناً اسی خیال کے ماتحت کی گئی تھیں.اسی طرح
سر بر آوردہ دشمنوں اور مفتوح رئیسوں کی لڑکیوں کے ساتھ بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی
شادیاں سیاسی اغراض کے ماتحت وقوع میں آئی تھیں.باقی شادیاں اس نیت سے تھیں
کہ تا آپ کو اولا در بینہ حاصل ہو جاوے جس کی آپ کو بہت آرزو رہتی تھی.“
یہ اس شخص کی رائے ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگاروں میں عناد اور تعصب کے لحاظ
سے غالباً صف اول میں ہے اور گو مار گولیس صاحب کی یہ رائے غلطی سے بالکل پاک نہیں ہے.مگر
اس سے یہ ثبوت ضرور ملتا ہے کہ صداقت کس طرح ایک عنید دل کو بھی مغلوب کر سکتی ہے.والفضل
ما شهدت به الاعداء
،،
دو فرضی واقعات جنگ بدر کے حالات کے بعد واقد کی اور بعض دوسرے مؤرخین نے دو ایسے
واقعات درج کئے ہیں جن کا کتب حدیث اور صحیح تاریخ روایات میں نشان نہیں
ملتا اور در ایتا بھی غور کیا جائے تو وہ درست ثابت نہیں ہوتے مگر چونکہ ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلاف ایک ظاہری صورت اعتراض کی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے بعض عیسائی مؤرخین نے حسب
عادت نہایت ناگوار صورت میں ان کا ذکر کیا ہے.یہ فرضی واقعات یوں بیان کئے گئے ہیں کہ مدینہ میں
ایک عورت عصماء نامی رہتی تھی جو اسلام کی سخت دشمن تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت
زہر اگلتی رہتی تھی اور اپنے اشتعال انگیز اشعار میں لوگوں کو آپ کے خلاف بہت اکساتی تھی اور آپ کے
قتل پر ابھارتی تھی.آخر ایک نابینا صحابی عمیر بن عدی نے اشتعال میں آ کر رات کے وقت اس کے گھر
میں جبکہ وہ سوئی ہوئی تھی اُسے قتل کر دیا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو
آپ نے اس صحابی کو ملامت نہیں فرمائی بلکہ ایک گونہ اس کے فعل
کی تعریف کی یا دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا
ہے کہ ایک بڑھا یہودی ابو عفک نامی مدینہ میں رہتا تھا.یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
اشتعال انگیز شعر کہتا تھا اور کفار کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور آپ کو قتل کر دینے کے لیے ابھارتا تھا.آخر ایک دن اُسے بھی ایک صحابی سالم بن عمیر نے غصہ میں آکر رات کے وقت اُس کے گھر کے صحن میں
ل : مارگولیس صفحه ۱۷۶ ، ۱۷۷
: ابن سعد جلد ۲ صفحه ۱۸ و ابن هشام جلد ۳ صفحه ۹۱
Page 520
۵۰۵
قتل کر دیا.اور واقدی اور ابن ہشام نے بعض وہ اشتعال انگیز اشعار بھی نقل کئے ہیں جو عصماً اور
ابوعفک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہے تھے.ان دو واقعات کو سرولیم میور وغیرہ نے
نہایت ناگوار صورت میں اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے.مگر حقیقت یہ ہے کہ جرح اور تنقید کے سامنے یہ
واقعات درست ثابت ہی نہیں ہوتے.پہلی دلیل جو ان کی صحت کے متعلق شبہ پیدا کرتی ہے یہ ہے کہ کتب
احادیث میں ان واقعات کا ذکر نہیں پایا جاتا یعنی کسی حدیث میں قاتل یا مقتول کا نام لے کر اس قسم کا کوئی
واقعہ بیان نہیں کیا گیا.بلکہ حدیث تو الگ رہی بعض مؤرخین نے بھی ان
کا ذکر نہیں کیا ؛ حالانکہ اگر اس قسم
کے واقعات واقعی ہوئے ہوتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ کتب حدیث اور بعض کتب تاریخ ان کے ذکر سے
خالی ہوتیں.اس جگہ یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ چونکہ ان واقعات سے بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ کے خلاف ایک گونہ اعتراض وارد ہوتا تھا.اس لئے محدثین اور بعض مؤرخین نے ان کا ذکر
ترک کر دیا ہوگا کیونکہ اول تو یہ واقعات ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جن میں وہ وقوع پذیر ہوئے
قابل اعتراض نہیں ہیں.دوسرے جو شخص حدیث و تاریخ کا معمولی مطالعہ بھی رکھتا ہے اس سے یہ بات مخفی
نہیں ہو سکتی کہ مسلمان محد ثین اور مؤرخین نے کبھی کسی روایت کے ذکر کو محض اس بنا پر ترک نہیں کیا کہ اس
سے اسلام اور بانی اسلام پر بظاہر اعتراض وارد ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مسلمہ طریق تھا کہ جس
بات کو بھی وہ از روئے روایت صحیح پاتے تھے اُسے نقل کرنے میں وہ اس کے مضمون کی وجہ سے قطعاً کوئی
تأمل نہیں کرتے تھے.بلکہ اُن میں سے بعض محدثین اور اکثر مورخین کا تو یہ طریق تھا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق جو بات بھی انہیں پہنچتی تھی خواہ وہ روایت و درایت دونوں لحاظ سے
کمزور اور نا قابل اعتماد ہو وہ اُسے دیانتداری کے ساتھ اپنے ذخیرہ میں جگہ دے دیتے تھے اور اس بات کا
فیصلہ مجتہد علماء پر یا بعد میں آنے والے محققین پر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ اصول روایت و درایت کے مطابق
ل : ابن سعد جلد ۲ صفحه ۹۱ وابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۰
۲ : ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۰ ، ۹۱ و مغازی الصادقه لواقدی صفحه ۱۲۳ ، ۱۲۵
: ابوداؤ د کتاب الحدود باب الحکم فی من سب میں بیشک ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو عصما کے قتل کے واقعہ سے
کچھ ملتا جلتا ہے لیکن اول تو اس میں قاتل و مقتول کے نام بیان نہیں کئے گئے دوسرے اس کی بعض تفصیلات بھی اس واقعہ کی
تفصیل سے نہیں ماتیں.علاوہ ازیں اسی باب کی اگلی حدیث میں واقعہ کو ایک بالکل ہی مختلف صورت میں بیان کیا گیا ہے
جس سے روایت کا اضطراب ظاہر ہوتا ہے.
Page 521
صحیح و سقیم کا خود فیصلہ کر لیں اور ایسا کرنے میں اُن کی نیت یہ ہوتی تھی کہ کوئی بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ کی طرف منسوب ہوتی ہے خواہ وہ درست نظر آئے یا غلط وہ جمع ہونے سے نہ رہ
جاوے.یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی ابتدائی کتابوں میں ہر قسم کے رطب و یابس کا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے مگر اس
کے یہ معنے نہیں ہیں کہ وہ سب قابل قبول ہیں بلکہ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ان میں سے کمزور کو مضبوط سے
جدا کر دیں.بہر حال اس بات میں ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں کہ کسی مسلمان محدث یا مؤرخ نے کبھی کسی
روایت کو محض اس بنا پر رد نہیں کیا کہ وہ بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی شان کے خلاف ہے یا
یہ کہ اس کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے.چنانچہ کعب بن
اشرف اور ابو رافع یہودی کے قتل کے واقعات جو عصماء اور ابو عفک کے مزعومہ واقعات سے بالکل ملتے
جلتے ہیں اور جن کا بیان آگے چل کر اپنے اپنے موقع پر آئے گا حدیث و تاریخ کی تمام کتابوں میں پوری
پوری صراحت اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور کسی مسلمان را وی یا محدث یا مورخ نے ان کے
بیان کو ترک نہیں کیا.اندریں حالات عصماء اور ابو عفک یہودی کے قتل کا ذکر کسی حدیث میں نہ پایا جانا،
بلکہ ابتدائی مؤرخین میں سے بعض مؤرخین کا بھی اس کے متعلق خاموش ہونا اس بات کو قریباً قریباً یقینی طور
پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ قصے بناوٹی ہیں اور کسی طرح بعض روایتوں میں راہ پا کر تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں.پھر
اگر ان قصوں کی تفصیلات کا مطالعہ کیا جاوے تو ان کا بناوٹی ہونا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے.مثلاً عصماء کے
قصہ میں ابن سعد وغیرہ کی روایت میں قاتل کا نام عمیر بن عدی بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے مقابلہ میں
ابن درید کی روایت میں قاتل کا نام عمیر بن عدی نہیں بلکہ مشمیر ہے.سہیلکی ان دونوں ناموں کو غلط قرار
دے کر یہ کہتا ہے کہ دراصل عصماء کو اس کے خاوند نے قتل کیا تھا.جس کا نام روایتوں میں یزید بن زید
بیان ہوا ہے.اور پھر بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مذکورہ بالا لوگوں میں سے کوئی بھی عصماء کا قاتل
نہیں تھا بلکہ اس کا قاتل ایک نامعلوم الاسم شخص تھا جو اسی کی قوم میں سے تھا.مقتولہ کا نام ابن سعد وغیرہ
نے عصماء بنت مردان بیان کیا ہے.لیکن علامہ عبد البر کا یہ قول ہے کہ وہ عصماء بنت مروان نہیں تھی بلکہ
دراصل عمیر نے اپنی بہن بنت عدی کو قتل کیا تھا.ہے قتل کا وقت ابن سعد نے رات کا درمیانی حصہ لکھا ہے
لیکن زرقانی کی روایت سے دن یا زیادہ سے زیادہ رات کا ابتدائی حصہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ
ل : زرقانی جلد اصفحه ۴۵۳
۳ : ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۱
: الروض الانف جلد ۲ صفحه ۳۶۴
: زرقانی جلد اصفحه ۴۵۴ ۵: استیعاب جلد ۲ صفحه ۴۴۰
Page 522
۵۰۷
بیان کیا گیا ہے کہ مقتولہ اس وقت کھجور میں بیچ رہی تھی.دوسرا واقعہ ابو عفک کے قتل کا ہے اس میں ابن سعد اور واقدی وغیرہ نے قاتل کا نام سالم بن عمیر لکھا
ہے لیکن بعض روایتوں میں اس کا نام سالم بن عمرو بیان ہوا ہے.اور ابن عقبہ نے سالم بن عبداللہ بیان کیا
ہے.اسی طرح ابو عفک مقتول کے متعلق ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ یہودی تھا لیکن واقدی اسے یہودی
نہیں لکھتا.پھر ابن سعد اور واقد کی دونوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سالم نے خود جوش میں آ کر ابو عفک کو
قتل کر دیا تھا، لیکن ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے
قتل کیا گیا تھا.زمانہ قتل کے متعلق بھی ابن سعد اور واقدی اسے عصماء کے
قتل کے بعد رکھتے ہیں لیکن
ابن اسحاق اور ابوالربیع اسے عصماء کے قتل سے پہلے بیان کرتے ہیں.یہ جملہ اختلافات اس بات کے
متعلق قوی شبہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ قصے جعلی اور بناوٹی ہیں یا اگر ان میں کوئی حقیقت ہے تو وہ ایسی مستور
ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے اور کس نوعیت کی ہے.ایک اور دلیل ان واقعات کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ ان دونوں قصوں کا زمانہ وہ بیان کیا گیا ہے
جس کے متعلق جملہ مؤرخین کا اتفاق ہے کہ اس وقت تک ابھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی
جھگڑا یا تنازعہ رونما نہیں ہوا تھا؛ چنانچہ تاریخ میں غزوہ بنی قینقاع کے متعلق یہ بات مسلّم طور پر بیان ہوئی
ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ پہلی لڑائی تھی جو وقوع میں آئی اور یہ کہ بنو قینقاع وہ پہلے
یہودی تھے جنہوں نے اسلام کی عداوت میں عملی کا رروائی کی ہے پس یہ کس طرح قبول کیا جاسکتا ہے کہ اس
غزوہ سے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس قسم کا کشت وخون ہو چکا تھا اور پھر اگر غزوہ بنو قینقاع
سے قبل ایسے واقعات ہو چکے تھے تو یہ ناممکن تھا کہ اس غزوہ کے بواعث وغیرہ کے بیان میں ان واقعات کا
ذکر نہ آتا.کم از کم اتنا تو ضروری تھا کہ یہودی لوگ جو ان واقعات کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف ایک
ظاہری رنگ اعتراض کا پیدا کر سکتے تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ عملی چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی ہے
ان واقعات کے متعلق واویلا کرتے.مگر کسی تاریخ میں حتیٰ کہ خودان مؤرخین کی کتب میں بھی جنہوں نے
یہ قصے روایت کئے ہیں قطعا یہ ذکر نہیں آتا کہ مدینہ کے یہود نے کبھی کوئی ایسا اعتراض کیا ہوا اور اگر کسی
ا : زرقانی جلد اصفحه ۴۵۴ ۲ : زرقانی جلد اصفحه ۴۵۵ ۳ : اصابہ واستيعاب ذکر سالم بن عمیر ے
: مغازی الصادقه صفحه ۱۲۵ ۵ : ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۰
ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۰ وزرقانی جلد اصفه ۴۵۳
کے ابن سعد جلد ۲ صفحه ۱۹ نیز ابن ہشام وطبری
Page 523
۵۰۸
شخص کو یہ خیال پیدا ہو کہ شاید انہوں نے اعتراض اٹھایا ہو مگر مسلمان مؤرخین نے اس کا ذکر نہ کیا ہو
تو یہ ایک غلط اور بے بنیاد خیال ہوگا کیونکہ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کبھی کسی مسلمان محدّث یا مورخ نے
مخالفین کے کسی اعتراض پر پردہ نہیں ڈالا؛ چنانچہ مثلاً جب سریہ نخلہ والے قصہ میں مشرکین مکہ نے
مسلمانوں کے خلاف اشہر حرم کی بے حرمتی کا الزام لگایا تو مسلمان مؤرخین نے کمال دیانت داری سے اُن
کے اس اعتراض کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا.پس اگر اس موقع پر بھی یہود کی طرف سے کوئی اعتراض
ہوا ہوتا تو تاریخ اس کے ذکر سے خالی نہ ہوتی.الغرض جس جہت سے بھی دیکھا جاوے یہ قصے صحیح ثابت
نہیں ہوتے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کسی مخفی دشمن اسلام نے کسی مسلمان کی طرف منسوب کر کے یہ
قصے بیان کر دیئے تھے اور پھر وہ مسلمانوں کی روایتوں میں دخل پاگئے اور یا کسی کمزور مسلمان نے اپنے قبیلہ
کی طرف یہ جھوٹا فخر منسوب کرنے کے لیے کہ اس سے تعلق رکھنے والے آدمیوں نے بعض موذی کافروں
کو قتل کیا تھا یہ روایتیں تاریخ میں داخل کر دیں.واللہ اعلم.یہ تو وہ اصل حقیت ہے جو ان واقعات کی معلوم ہوتی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے اگر یہ
واقعات درست بھی ہوں تو پھر بھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن کے ماتحت وہ وقوع پذیر ہوئے وہ قابل
اعتراض نہیں سمجھے جا سکتے.ان ایام میں جو نازک حالت مسلمانوں کی تھی اس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے.ان کا
حال بعینہ اس شخص کی طرح ہو رہا تھا جو ایک ایسی جگہ میں گھر جاوے جس کے چاروں طرف دور دور تک
خطر ناک آگ شعلہ زن ہو اور اس کے لیے کوئی راستہ باہر نکلنے کا نہ ہوا اور پھر اس کے پاس بھی وہ لوگ
کھڑے ہوں جو اس کے جانی دشمن ہیں.مسلمانوں کی ایسی نازک حالت میں اگر کوئی شریر اور فتنہ پرداز
شخص ان کے آقا اور سردار کے خلاف اشتعال انگیز شعر کہ کہہ کر لوگوں کو اس کے خلاف اکساتا اور اس کے
قتل پر دشمنوں کو ابھارتا تھا تو اس زمانہ کے حالات کے ماتحت اس کا علاج سوائے اس کے اور کیا ہوسکتا تھا
کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جاتا اور پھر یہ قتل بھی مسلمانوں کی طرف سے انتہائی اشتعال کی حالت میں ہوا.جس حالت میں کہ معمولی قتل بھی قصاص کے قابل نہیں سمجھا جاتا ؛ چنانچہ مسٹر مار گولیس جیسا شخص بھی جو
عموماً ہر امر میں مخالفانہ پہلو لیتا ہے ان واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کو قابل ملامت نہیں قرار دیتا؛
چنانچہ مسٹر مار گولیس لکھتے ہیں:
چونکہ عصماء نے اپنے اشعار میں اگر وہ اس کی طرف صحیح طور پر منسوب کئے گئے ہیں
محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے قتل پر اُن کے دشمنوں کو عمدا ابھارا تھا.اس لیے اس کا قتل خواہ اُسے
Page 524
دنیا کے کسی معیار کے مطابق ہی جج کیا جاوے ایک بے بنیاد اور ظالمانہ فعل نہیں سمجھا جاسکتا اور
پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیئے کہ اشتعال انگیزی کا وہ طریق جو ہجو کے اشعار کی صورت میں
اختیار کیا گیا وہ عرب جیسے ملک میں دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ خطرناک نتائج پیدا
کر سکتا تھا.اور یہ بات کہ صرف مجرموں کو ہی قتل کیا گیا عرب کے رائج الوقت دستور پر ایک
بہت بڑی اصلاح تھی.کیونکہ عربوں میں اشتعال انگیز اشعار کی وجہ سے صرف افراد تک معاملہ
محدود نہیں رہتا تھا بلکہ سالم کے سالم قبائل میں خطر ناک جنگ کی آگ مشتعل ہو جایا کرتی تھی.اس کی جگہ اسلام میں یہ صیح اصول قائم کیا گیا کہ مُجرم کی سزا صرف مجرم کو ہونی چاہیئے نہ کہ
،،
اس کے عزیز واقارب کو بھی.مسٹر مار گولیس کو اگر ان قتلوں کے متعلق کوئی اعتراض ہے، تو اس طریق کی وجہ سے ہے جو اختیار کیا گیا
یعنی یہ کہ کیوں نہ ان کے جرم کا باقاعدہ اعلان کر کے انہیں باضابطہ طور پر قتل کی سزا دی گئی.سواس کا پہلا
جواب تو یہ ہے کہ اگر ان واقعات کو درست بھی سمجھا جاوے تو وہ بعض مسلمانوں کے محض انفرادی فعل تھے
جوان سے سخت اشتعال کی حالت میں سرزد ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم نہیں دیا تھا
جیسا کہ ابن سعد کے بیان سے یقینی طور پر پایا جاتا ہے.دوسرے اگر بالفرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا حکم ہی سمجھا جاوے تو پھر بھی یقیناً اس زمانہ کے حالات ایسے تھے کہ اگر عصماء اور ابو عفک کے قتل کے
متعلق با قاعدہ طور پر ضابطہ کا طریق اختیار کیا جاتا اور مقتولین کے متعلقین کو پیش از وقت اطلاع ہو جاتی
کہ ہمارے آدمی قتل کئے جائیں گے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے تھے اور اس بات کا سخت
اندیشہ تھا کہ یہ واقعات مسلمانوں اور یہودیوں اور نیز مسلمانوں اور مشرکین مدینہ کے درمیان ایک وسیع
جنگ کی آگ مشتعل کر دیتے.تعجب ہے کہ مسٹر مار گولیس نے جہاں محض قتل کے فعل کو عرب کے مخصوص
حالات کے ماتحت جائز قرار دیا ہے وہاں طریقہ قتل کے متعلق ان کی نظر اس زمانہ کے مخصوص حالات
تک کیوں نہیں پہنچی.اگر وہ اس پہلو میں بھی اس وقت کے حالات کو مدنظر رکھتے تو غالباً انہیں یقین ہو
جاتا کہ جو طریق اختیار کیا گیا وہی اس وقت کے حالات اور امن عامہ کے مفاد کے لیے مناسب اور
ضروری تھا لیکن اس کے متعلق زیادہ تفصیلی بحث ہم انشاء اللہ کعب بن اشرف کے قتل کے بیان میں
ل : محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) مصنفہ مارگولیس صفحه ۲۷۸ ، ۲۷۹
: ابن سعد جلد ۳ صفحه ۱۸ ، ۱۹
Page 525
۵۱۰
ہدیہ ناظرین کریں گے.خلاصہ کلام یہ کہ اول تو عصماء اور ابو عفک یہودی کے قتل کے واقعات روایا اور درایتاً درست
ثابت ہی نہیں ہوتے اور اگر بالفرض انہیں درست سمجھا بھی جاوے تو وہ اس زمانہ کے حالات کے ماتحت
قابل اعتراض نہیں سمجھے جاسکتے اور پھر یہ کہ جو بھی صورت ہو یہ واقعات قتل بہر حال بعض مسلمانوں کے
انفرادی افعال تھے جو سخت اشتعال کی حالت میں اُن سے سرزد ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اُن کے متعلق حکم نہیں دیا تھا.
Page 526
۵۱۱
قبائل نجد اور یہود کے ساتھ جنگ کا آغاز
حضرت فاطمہ اور حفصہ کی شادی
بعض متفرق واقعات
غزوہ قرقرة الكدر شوال ۲ ہجری یہ بتایا جاچکا ہے کہ ہجرت کے بعد قریش مکہ نے مختلف قبائل
عرب کا دورہ کر کے بہت سے قبائل کو مسلمانوں کا جانی دشمن
بنا دیا تھا.ان قبائل میں طاقت اور جتھے کے لحاظ سے زیادہ اہم عرب کے وسطی علاقہ نجد کے رہنے والے
دو قبیلے تھے.جن کا نام بنوسلیم اور بنو غطفان تھا اور قریش مکہ نے ان دو قبائل کو خصوصیت کے ساتھ اپنے
ساتھ گانٹھ کر مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا تھا.چنانچہ سرولیم میور لکھتے ہیں کہ
66
قریش مکہ نے اب اپنی توجہ اس نجدی علاقہ کی طرف پھیری اور اس علاقہ کے قبائل کے
ساتھ آگے سے بھی زیادہ گہرے تعلقات قائم کر لئے اور اس وقت کے بعد قبائل سلیم وغطفان
محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے سخت دشمن ہو گئے اور ان کی اس دشمنی نے مسلمانوں کے خلاف عملی
صورت اختیار کر لی.چنانچہ قریش کی اشتعال انگیزی اور ابوسفیان کے عملی نمونہ کے نتیجہ میں
انہوں نے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تجویز پختہ کر لی.“
چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو ابھی آپ کو مدینہ میں پہنچے
ہوئے صرف چند دن ہی ہوئے تھے کہ آپ کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ قبائل سلیم وغطفان کا ایک
بڑا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی نیت سے قرقرۃ الکدر میں جمع ہو رہا ہے." جنگ بدر کے اس قدر قریب
اس اطلاع کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب قریش کا لشکر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے کی نیت سے مکہ
سے نکلا تھا تو رؤساء قریش نے اسی وقت قبائل سلیم و غطفان کو یہ پیغام بھیج دیا ہوگا کہ تم دوسری طرف سے
ابن ہشام حالات غزوہ بنی سلیم با لکدر : ابن سعد
لائف آف محمد صفحه ۲۳۶، ۲۳۷
Page 527
۵۱۲
مدینہ پر حملہ آور ہو جاؤ.یا یہ بھی ممکن ہے کہ جب ابوسفیان اپنے قافلہ کے ساتھ بیچ کر نکل گیا تو اس نے کسی
قاصد وغیرہ کے ذریعہ ان قبائل کو مسلمانوں کے خلاف نکلنے کی تحریک کی ہو.بہر حال ابھی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فارغ ہو کر مدینہ میں پہنچے ہی تھے کہ یہ وحشتناک اطلاع موصول ہوئی کہ
قبائل سلیم و غطفان مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں.یہ خبر سن کر آپ فوراصحابہ کی ایک جمعیت کو ساتھ
لے کر پیش بندی کے طور پر نجد کی طرف روانہ ہو گئے لیکن جب آپ کئی دن کا تکلیف دہ سفر طے کر کے
موضع الکدر کے قرقره یعنی چٹیل میدان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بنوسلیم اور بنو غطفان کے لوگ لشکر اسلام کی
آمد آمد کی خبر پا کر پاس کی پہاڑیوں میں جا چھپے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں
مسلمانوں کا ایک دستہ روانہ فرمایا اور خود بطن وادی کی طرف بڑھے، مگر ان کا کچھ سراغ نہیں ملالے البتہ
ان کے اونٹوں کا ایک بڑا گلہ ایک وادی میں چرتا ہوا مل گیا جس پر قوانین جنگ کے ماتحت صحابہ نے قبضہ
کر لیا اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو واپس لوٹ آئے.ان اونٹوں کا چرواہا ایک سیار
نامی غلام تھا جو اونٹوں کے ساتھ قید کر لیا گیا تھا.اس شخص پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایسا اثر
ہوا کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت
اسے بطور احسان کے آزاد کر دیا ہے مگر وہ مرتے دم تک آپ کی خدمت سے جدا نہیں ہوا.کے
غزوہ سویق ذوالحجہ ہ ہجری بدر کے نتیجہ میں جو ماتم مکہ میں بپا ہوا تھا اسکا ذکر اوپرگزر چکا ہے.قریباً
سارے رؤساء قریش قتل ہو چکے تھے اور اب مکہ کی ریاست ابوسفیان بن
حرب کے حصہ میں آئی تھی.چنانچہ بدر کے بعد ابوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مقتولین بدر کا انتقام
نہ لے لے گا کبھی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے گا.اور نہ کبھی اپنے بالوں کو تیل لگائے گا.چنانچہ بدر کے
دو تین ماہ بعد ذوالحجہ کے مہینہ میں ابوسفیان دو سو سلح قریش کی جمعیت کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے نکلا
اور نجدی راستہ کی طرف سے ہوتا ہوا مدینہ کے پاس پہنچ گیا.یہاں پہنچ کر اس نے اپنے لشکر کو تو مدینہ سے
کچھ فاصلہ پر چھوڑا اور خود رات کی تاریکی کے پردہ میں چھپتا ہوا یہودی قبیلہ بنونضیر کے رئیس حیی بن
اخطب کے مکان پر پہنچا اور اس سے امداد چاہی مگر چونکہ اس کے دل میں اپنے عہد و پیمان کی کچھ یاد باقی
تھی اس نے انکار کیا.پھر ابوسفیان اسی طرح چھپتا ہوا بنونضیر کے دوسرے رئیس سلام بن مشکم کے مکان پر
زرقانی
ابن سعد ۳: اسد الغابہ جلد ۵ صفحه ۱۲۴
ابن ہشام
ه: ابن سعد
Page 528
۵۱۳
گیا اور اس سے مسلمانوں کے خلاف اعانت کا طلب گار ہوا.اس بد بخت نے کمال جرات کے ساتھ
سارے عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر ابوسفیان کی بڑی آؤ بھگت کی اور اسے اپنے پاس رات کو مہمان
رکھا اور اس سے مسلمانوں کے حالات کے متعلق مخبری کی یا صبح ہونے سے قبل ابوسفیان وہاں سے نکلا
اور اپنے لشکر میں پہنچ کر اس نے قریش کے ایک دستے کو مدینہ کے قریب عریض کی وادی میں چھاپہ مارنے
کے لئے روانہ کر دیا.یہ وہ وادی تھی جہاں ان ایام میں مسلمانوں کے جانور چرا کرتے تھے اور جو مدینہ
سے صرف تین میل پر تھی اور غالباً اس کا حال ابو سفیان کو سلام بن مشکم سے معلوم ہوا ہوگا.جب قریش کا یہ
دستہ وادی عریض میں پہنچا تو خوش قسمتی سے اس وقت مسلمانوں کے جانور وہاں موجود نہ تھے.البتہ ایک
مسلمان انصاری اور اس کا ایک ساتھی اس وقت وہاں موجود تھے.قریش نے ان دونوں کو پکڑ کر ظالمانہ
طور پر قتل کر دیا.اور پھر کھجوروں کے درختوں کو آگ لگا کر " اور وہاں کے مکانوں اور جھونپڑوں کو جلا کر ھے
ابوسفیان کی قیام گاہ کی طرف واپس لوٹ گئے.ابوسفیان نے اس کامیابی کو اپنی قسم کے پورا ہونے کے لئے
کافی سمجھ کر لشکر کو واپسی کا حکم دیا.دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوسفیان کے حملہ کی اطلاع
ہوئی تو آپ صحابہ کی ایک جماعت ساتھ لے کر اس کے تعاقب میں نکلے ،مگر چونکہ ابوسفیان اپنی قسم کے ایفا
کو مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا.وہ ایسی سراسیمگی کے ساتھ بھا گا کہ مسلمان اس کے لشکر کو پہنچ نہیں سکے
اور بالآخر چند دن کی غیر حاضری کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ آئے.اس غزوہ
کو غزوہ سویق کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابوسفیان مکہ کو واپس لوٹا تو تعاقب کے خیال کی وجہ سے
کچھ تو گھبراہٹ میں اور کچھ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لئے وہ اپنا سامان رسد جو زیادہ تر سویق یعنی ستو کے
تھیلوں پر مشتمل تھا راستہ میں پھینکتا گیا تھا.عیدالاضحی ذوالحجہ بجری عیدالفطر کے ذکر میں اسلامی عیدوں کا فلسفہ بیان کیا جا
چکا ہے.اس سال
ماہ ذی الحجہ میں دوسری اسلامی عید یعنی عیدالاضحی مشروع ہوئی جو ماہ ذوالحجہ کی
دسویں تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں منائی جاتی ہے.اس عید میں علاوہ نماز کے جو ہر سچے مسلمان کی حقیقی
عید ہے.ہر ذی استطاعت مسلمان کے لئے واجب ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چوپایہ جانور قربان
کر کے اس کا گوشت اپنے عزیز واقارب اور دوستوں اور ہمسایوں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کرے
ابن ہشام و ابن سعد
ابن ہشام
ابن ہشام
ه : ابن سعد
: ابن ہشام وابن سعد
طبری صفحه ۱۳۶۲
Page 529
۵۱۴
اور خود بھی کھائے.چنانچہ عید الاضحی کے دن اور اس کے بعد دو دن تک تمام اسلامی دنیا میں لاکھوں کروڑوں
جانور فی سبیل
اللہ قربان کئے جاتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے اندر عملی طور پر اس عظیم الشان قربانی کی
یا دزندہ رکھی جاتی ہے جو حضرت
ابراہیم اور حضرت اسمعیل اور حضرت ہاجرہ نے پیش کی اور جس کی بہترین
مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور ہر ایک مسلمان کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے آقا
و مالک کی راہ میں اپنی جان اور مال اور اپنی ہر ایک چیز قربان کر دینے کے واسطے تیار ہے.یہ عید بھی
عیدالفطر کی طرح ایک عظیم الشان اسلامی عبادت
کی تکمیل پر منائی جاتی ہے اور وہ عبادت حج ہے جس کا ذکر
انشاء اللہ اپنے موقع پر آئے گا.حضرت فاطمہ کا نکاح ذوالحجہ ۲ ہجری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بیان میں حضرت
فاطمہ کا ذکر گزر چکا ہے جمہور مورخین کے قول کے
مطابق حضرت فاطمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اولاد میں سب سے چھوٹی تھیں جو حضرت خدیجہ
کے بطن سے پیدا ہوئی.اور آپ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ کو عزیز رکھتے تھے.اور
اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے وہی اس امتیازی محبت کی سب سے زیادہ اہل تھیں.اب ان کی عمر کم و بیش
پندرہ سال کی تھی اور شادی کے پیغامات آنے شروع ہو گئے تھے.سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے لئے
حضرت ابو بکر نے درخواست کی ،مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کر دیا.پھر حضرت عمرؓ نے عرض
کیا مگر ان کی درخواست بھی منظور نہ ہوئی ہے اس کے بعد ان دونوں بزرگوں نے یہ سمجھ کر کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حضرت علیؓ کے متعلق معلوم ہوتا ہے حضرت علی سے تحریک کی کہ تم فاطمہ کے متعلق
درخواست کر دو.حضرت علیؓ نے جو غالباً پہلے سے خواہش مند تھے مگر بوجہ حیا خاموش تھے فوراً آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست پیش کر دی.دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو خدائی وحی کے ذریعہ یہ اشارہ ہو چکا تھا کہ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علیؓ سے ہونی چاہئے.چنانچہ حضرت علی نے درخواست پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ
ہو چکا ہے.پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا وہ بوجہ حیا کے خاموش رہیں..یہ ایک طرح سے اظہار
رضا تھا.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو جمع کر کے حضرت علی
ترمذی باب فضل فاطمه
نسائی کتاب النکاح باب ترویج المراة مثلها
: اصابه
: ابن سعد جلد ۸ صفحه ۱۱ ۱۲ ۵: زرقانی جلد ۲ صفحه ۵۰۴ : ابن سعد جلد ۸ صفحه ۱۲
Page 530
۵۱۵
اور فاطمہ کا نکاح پڑھ دیا.یہ ۲ ہجری کی ابتدا یا وسط کا واقعہ ہے.اس کے بعد جنگ بدر ہو چکی تو غالباً
ماہ ذوالحجہ ہجری میں رخصتانہ کی تجویز ہوئی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
علی کو بلا کر دریافت
فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کی ادائیگی کے لئے کچھ ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے عرض کیا: یا رسول اللہ !
میرے پاس تو کچھ نہیں.آپ نے فرمایا وہ زرہ کیا ہوئی ہے جو میں نے اس دن (یعنی بدر کے مغائم میں
سے ) تمہیں دی تھی ؟ حضرت علی نے عرض کیا وہ تو ہے.آپ نے فرمایا.بس وہی لے آؤ.چنانچہ یہ
زره چارسواسی درہم میں فروخت کر دی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رقم میں سے شادی کے
اخراجات مہیا کئے.جو جہیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو دیا وہ ایک بیل دار چادر، ایک چمڑے
کا گدیلا جس کے اندر کجھور کے خشک پتے بھرے ہوئے تھے اور ایک مشکیزہ تھا.اور ایک روایت میں
ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے جہیز میں ایک چکی بھی دی تھی.جب یہ سامان ہو چکا تو مکان کی فکر
ہوئی.حضرت علی اب تک غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے کسی حجرہ وغیرہ میں رہتے تھے
مگر شادی کے بعد یہ ضروری تھا کہ کوئی الگ مکان ہو جس میں خاوند بیوی رہ سکیں.چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ اب تم کوئی مکان تلاش کرو جس میں تم دونوں رہ سکو.حضرت علی نے عارضی طور پر ایک مکان کا انتظام کیا اور اس میں حضرت فاطمہ کا رخصتا نہ ہو گیا.اسی دن
رخصتانہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور تھوڑا سا پانی منگا کر اس پر
دعا کی اور پھر وہ پانی حضرت فاطمہ اور حضرت علی ہر دو پر یہ الفاظ فرماتے ہوئے چھڑ کا.اَللَّهُمَّ بَارِکُ
فِيهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكَ لَهُمَا نَسْلَهُمَا یعنی ”اے میرے اللہ ! تو ان دونوں کے باہمی
تعلقات میں برکت دے اور ان کے ان تعلقات میں برکت دے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ قائم ہوں
اور ان کی نسل میں برکت دے.اور پھر آپ اس نئے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کر واپس تشریف لے
آئے.اس کے بعد جو ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت
فاطمہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حارثہ بن نعمان انصاری کے پاس چند ایک مکانات
زرقانی جلد ۶ صفحه ۴ ، ۶،۵
: اصابه ۳ : طبری صفحه ۱۳۶۷
ابوداؤ د کتاب النکاح باب الرجل يدخل ه: اصابه
نسائی بحوالہ تلخیص الصحاح كتاب النکاح
ا اصابه
زرقانی
: اصابه ۹: ابن سعد جلد ۸ صفحه ۱۴
Page 531
۵۱۶
ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ وہ اپنا کوئی مکان خالی کر دیں.آپ نے فرمایا وہ ہماری خاطر اتنے مکانات
پہلے ہی خالی کر چکے ہیں، اب مجھے تو انہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے.حارثہ کو کسی طرح اس کا علم ہوا تو
وہ بھاگے آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! میرا جو کچھ ہے وہ حضور کا ہے
اور واللہ جو چیز آپ مجھ سے قبول فرما لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ خوشی پہنچاتی ہے بہ نسبت اس چیز کے جو
میرے پاس رہتی ہے اور پھر اس مخلص صحابی نے باصرار اپنا ایک مکان خالی کروا کے پیش کر دیا اور حضرت
علی اور فاطمہ وہاں اٹھ گئے.اس جگہ یہ ذکر بھی بے موقع نہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد میں صرف حضرت
فاطمہ ہی آپ کی وفات کے بعد زندہ رہیں باقی سب بچے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے.حضرت.فاطمہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد میں صرف انہی کی نسل کا
سلسلہ قائم رہا.چنانچہ مسلمانوں میں سادات کی قوم انہی کی نسل سے ہے.حضرت فاطمہ نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ ماہ بعد وفات پائی ہے
غزوہ بنو قینقاع اواخر ۲ ہجری یہ بتایا جا چکا ہے کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے
ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے اس وقت مدینہ میں
یہود کے تین قبائل آباد تھے.ان کے نام بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنوقریظہ تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے مدینہ میں آتے ہی ان قبائل کے ساتھ امن وامان کے معاہدے کر لئے اور آپس میں صلح اور امن کے
ساتھ رہنے کی بنیاد ڈالی.معاہدہ کی رو سے فریقین اس بات کے ذمہ دار تھے کہ مدینہ میں امن وامان قائم
رکھیں اور اگر کوئی بیرونی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں سے شروع شروع میں تو یہود
اس معاہدہ کے پابند رہے اور کم از کم ظاہری طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا پیدا نہیں کیا
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں زیادہ اقتدار حاصل کرتے جاتے ہیں تو ان کے تیور
بدلنے شروع ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کا تہیہ کر لیا اور اس غرض
کے لئے انہوں نے ہر قسم کی جائز و نا جائز تدابیر اختیار کرنی شروع کیں حتی کہ انہوں اس بات کی کوشش
سے بھی دریغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کر کے خانہ جنگی شروع کرا دیں.چنانچہ روایت آتی
ابن سعد جلد ۸ صفحه ۱۴
بخاری
: اصابه
ابن ہشام حالات معاہدہ یہود وطبری صفحه ۱۳۹۵
Page 532
۵۱۷
ہے کہ ایک موقع پر قبیلہ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے باہم محبت واتفاق سے باتیں
کر رہے تھے کہ بعض فتنہ پرداز یہود نے اس مجلس میں پہنچ کر جنگ بعاث کا تذکرہ شروع کر دیا.یہ وہ
خطر ناک جنگ تھی جو ان دو قبائل کے درمیان ہجرت سے چند سال قبل ہوئی تھی اور جس میں اوس اور خزرج
کے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے گئے تھے.اس جنگ کا ذکر آتے ہی بعض جو شیلے
لوگوں کے دلوں میں پرانی یاد تازہ ہوگئی اور گزشتہ عداوت کے منظر آنکھوں کے سامنے پھر گئے.نتیجہ یہ ہوا
کہ با ہم نوک جھونک اور طعن و تشنیع سے گزر کر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسی مجلس میں مسلمانوں کے اندر
تلوار کھیچ گئی مگر خیر گزری کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ مہاجرین کی
ایک جماعت کے ساتھ فوراً موقع پر تشریف لے آئے اور فریقین کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور پھر ملامت بھی
فرمائی کہ تم میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کا طریق اختیار کرتے ہو اور خدا کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے
کہ اس نے اسلام کے ذریعہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے.انصار پر آپ کی اس نصیحت کا ایسا اثر ہوا کہ ان
کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنی اس حرکت سے تائب ہوکر ایک دوسرے سے بغلگیر ہو گئے.جب جنگ بدر ہو چکی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو باوجود ان کی قلت اور بے سروسامانی
کے قریش کے ایک بڑے جزار لشکر پر نمایاں فتح دی اور مکہ کے بڑے بڑے عمائد خاک میں مل گئے تو مدینہ
کے یہودیوں کی مخفی آتش حسد بھڑک اٹھی اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلم کھلا نوک جھونک شروع
کردی اور مجلسوں میں برملا طور پر کہنا شروع کیا کہ قریش کے لشکر کو شکست دینا کون سی بڑی بات تھی
ہمارے ساتھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مقابلہ ہوتو ہم بتادیں کہ کس طرح لڑا کرتے ہیں.حتی کہ ایک مجلس
میں انہوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اسی قسم کے الفاظ کہے.چنانچہ روایت آتی ہے کہ
جنگ بدر کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک دن یہودیوں کو جمع
کر کے ان کو نصیحت فرمائی اور اپنا دعویٰ پیش کر کے اسلام کی طرف دعوت دی.آپ کی اس پر امن اور
ہمدردانہ تقریر کا رؤسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تم شاید چند
قریش کو قتل کر کے مغرور ہو گئے ہو وہ لوگ لڑائی کے فن سے نا واقف تھے.اگر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ
ہو تو تمہیں پتہ لگ جاوے کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں.کے یہود نے صرف عام دھمکی پر ہی اکتفا نہیں کی
ا تفسیر ابن جریر جلد ۴ صفحه ۱۶
طبری صفحه ۱۳۵۹ سطر ۱۴، ۱۵
ابو داؤد کتاب الخراج باب کیف کان اخراج الیہود وطبری صفحه ۱۳۶۰ وابن ہشام
Page 533
۵۱۸
بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بھی منصوبے شروع کر دیے تھے
کیونکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں طلحہ بن براء جو ایک مخلص صحابی تھے فوت ہونے لگے تو انہوں
نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مروں تو نماز جنازہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی
جاوے تا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر یہود کی طرف سے کوئی حادثہ گزر جاوے.الغرض جنگ بدر کے
بعد یہود نے کھلم کھلا شرارت شروع کر دی اور چونکہ مدینہ کے یہود میں بنو قینقاع سب میں زیادہ طاقتور اور
بہادر تھے اس لئے سب سے پہلے انہی کی طرف سے عہد شکنی شروع ہوئی.چنانچہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ اِنَّ
بَنِي قَيْنِقَاعَ كَانُوا أَوَّلَ يَهُودٍ نَقَضُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ بَدْرٍ اَظْهَرُوا
الْبَغْيَ وَالْحَسَدَ وَنَبَدُوا الْعَھد کے یعنی مدینہ کے یہودیوں میں سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس
معاہدہ کو تو ڑا جو ان کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا اور بدر کے بعد انہوں نے بہت
سرکشی شروع کر دی اور بر ملاطور پر بغض وحسد کا اظہار کیا اور عہد و پیمان کو توڑ دیا.مگر با وجود اس قسم کی باتوں کے مسلمانوں نے اپنے آقا کی ہدایت کے ماتحت ہر طرح سے صبر سے
کام لیا اور اپنی طرف سے کوئی پیش دستی نہیں ہونے دی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدہ کے بعد
جو یہود کے ساتھ ہوا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہود کی دلداری کا خیال رکھتے تھے.چنانچہ
ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کچھ اختلاف ہو گیا.یہودی نے حضرت موسی کی تمام انبیاء پر
فضیلت بیان کی.صحابی کو اس پر غصہ آیا اور اس نے یہودی کے ساتھ کچھ پتی کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو افضل الرسل بیان کیا.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ ناراض ہوئے
اور اس صحابی کو ملامت فرمائی اور کہا کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ تم خدا کے رسولوں کی ایک دوسرے پر فضیلت
بیان کرتے پھرو.اور پھر آپ نے موسی کی ایک جزوی فضیلت بیان کر کے یہودی کی دلداری فرمائی.مگر با وجود اس دلدا را نه سلوک کے یہودی اپنی شرارت میں ترقی کرتے گئے اور بالآخر خود یہود کی طرف
سے ہی جنگ کا باعث پیدا ہوا اور ان کی قلبی عداوت ان کے سینوں میں سما نہ سکی اور یہ اس طرح پر ہوا کہ
ایک مسلمان خاتون بازار میں ایک یہودی کی دکان پر کچھ سودا خریدنے کے لئے گئی.بعض شریر یہودیوں
نے جو اس وقت اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اسے نہایت او با شانہ طریق پر چھیڑا اور خود دوکاندار نے یہ
ا : اصابه جلد ۳ صفحه ۵۸۰
مسلم جلد ۲ باب من فضائل موسی صفحه ۳۰۸
ابن ہشام وطبری
: ابن سعد
Page 534
۵۱۹
شرارت کی کہ اس عورت کے تہہ بند کے نچلے کونے کو اس کی بے خبری کی حالت میں کسی کانٹے وغیرہ سے
اس کی پیٹھ کے کپڑے سے ٹانک دیا.نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ عورت ان کے اوباشانہ طریق کو دیکھ کر وہاں
سے اٹھ کر لوٹنے لگی تو وہ ہنگی ہوگئی.اس پر اس یہودی دوکاندار اور اس کے ساتھیوں نے زور سے ایک قہقہہ
لگایا اور ہنسنے لگ گئے.مسلمان خاتون نے شرم کے مارے ایک چیخ ماری اور مدد چاہی.اتفاق سے ایک
مسلمان اس وقت قریب موجود تھا.وہ لپک کر موقع پر پہنچا اور باہم لڑائی میں یہودی دوکاندار مارا گیا جس
پر چاروں طرف سے اس مسلمان پر تلوار میں برس پڑیں اور وہ غیور مسلمان وہیں پر ڈھیر ہو گیا.مسلمانوں کو
اس واقعہ کاعلم ہوا تو غیرت قومی سے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور دوسری طرف یہودی جو اس واقعہ کو
لڑائی کا بہانہ بنانا چاہتے تھے ہجوم کر کے اکٹھے ہو گئے اور ایک بلوہ کی صورت پیدا ہوگئی.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے رؤسائے بنو قینقاع کو جمع کر کے کہا کہ یہ طریق اچھا نہیں تم ان
شرارتوں سے باز آجاؤ اور خدا سے ڈرو.انہوں نے بجائے اس کے کہ اظہار افسوس وندامت کرتے
اور معافی کے طالب بنتے سامنے سے نہایت متمردانہ جواب دئے اور پھر وہی دھمکی دہرائی کہ بدر کی فتح
پر غرور نہ کرو، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ لگ جائے گا کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں.نا چا ر آپ
صحابہ کی ایک جمعیت کو ساتھ لے کر بنو قینقاع کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے.اب یہ آخری موقع تھا کہ
وہ اپنے افعال پر پشیمان ہوتے مگر وہ سامنے سے جنگ پر آمادہ تھے.الغرض جنگ کا اعلان ہوگیا
اور اسلام اور یہودیت کی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل پر نکل آئیں.اس زمانہ کے دستور کے مطابق
جنگ کا ایک طریق یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو کر بیٹھ جاتے تھے اور فریق مخالف قلعوں
کا محاصرہ کر لیتا تھا اور موقع موقع پر گاہے گاہے ایک دوسرے کے خلاف حملے ہوتے رہتے تھے.حتی کہ
یا تو محاصرہ کرنے والی فوج قلعہ پر قبضہ کرنے سے مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیتی تھی اور یہ محصورین کی فتح
سمجھی جاتی تھی اور یا محصورین مقابلہ کی تاب نہ لا کر قلعہ کا دروازہ کھول کر اپنے آپ کو فاتحین کے سپرد
کر دیتے تھے اس موقع پر بھی بنو قینقاع نے یہی طریق اختیار کیا اور اپنے قلعوں میں بند ہو کر بیٹھ
گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا اور پندرہ دن تک برابر محاصرہ جاری
رہا.بالآخر جب بنو قینقاع کا سارا زور اور غرور ٹوٹ گیا تو انہوں نے اس شرط پر اپنے قلعوں کے
دروازے کھول دئے کہ ان کے اموال مسلمانوں کے ہو جائیں گے، مگر ان کی جانوں اور ان کے
: خمیس جلد اصفحه ۴۷۰ : زرقانی جلد اصفحہ ۴۵۷ سطر ۲۷
ابن ہشام
Page 535
۵۲۰
اہل وعیال پر مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہو گا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور فرما لیا
کیونکہ گوموسوی شریعت کی رو سے یہ سب لوگ واجب القتل تھے اور معاہدہ کی رو سے ان لوگوں پر
موسوی شریعت کا فیصلہ ہی جاری ہونا چاہئے تھا.مگر اس قوم کا یہ پہلا جرم تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی رحیم و کریم طبیعت انتہائی سزا کی طرف جو ایک آخری علاج ہوتا ہے ابتدائی قدم پر مائل نہیں ہوسکتی
تھی ،لیکن دوسری طرف ایسے بد عہد اور معاند قبیلہ کامدینہ میں رہنا بھی ایک مارآستین کے پالنے سے کم نہ
تھا.خصوصاً جب اوس اور خزرج کا ایک منافق گروہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھا اور بیرونی جانب سے بھی
تمام عرب
کی مخالفت نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا.ایسے حالات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہی فیصلہ ہوسکتا تھا کہ بنو قینقاع مدینہ سے چلے جائیں.یہ سزا ان کے جرم کے مقابل میں اور نیز اس
زمانہ کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بہت نرم سزا تھی اور دراصل اس میں صرف خود حفاظتی کا پہلو بھی
مد نظر تھا.ورنہ عرب کی خانہ بدوش اقوام کے نزدیک نقل مکانی کوئی بڑی بات نہ تھی.خصوصاً جبکہ کسی قبیلہ کی
جائیدادیں زمینوں اور باغات کی صورت میں نہ ہوں جیسا کہ بنو قینقاع کی نہیں تھیں.اور پھر سارے کے
سارے قبیلہ کو بڑے امن وامان کے ساتھ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر آباد ہونے کا موقع مل
جاوے.چنانچہ بنو قینقاع بڑے اطمینان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے.ان کی روانگی کے
متعلق ضروری اہتمام اور نگرانی وغیرہ کا کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبادہ بن صامت
کے سپر دفرمایا تھا جو ان کے حلفاء میں سے تھے.چنانچہ عبادہ بن صامت چند منزل تک بنو قینقاع کے
ساتھ گئے اور پھر انہیں حفاظت کے ساتھ آگے روانہ کر کے واپس لوٹ آئے کے مال غنیمت جو مسلمانوں
کے ہاتھ آیا وہ صرف آلات حرب اور آلات پیشہ زرگری پر مشتمل تھا.ہے
بنو قینقاع کے متعلق بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے دروازے
کھول کر اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر د کر دیا تو ان کی بدعہدی اور بغاوت اور شرارتوں کی
وجہ سے آپ کا ارادہ ان کے جنگجو مردوں کو قتل کرا دینے کا تھا مگر عبد اللہ بن ابی بن سلول رئیس منافقین کی
سفارش پر آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا لیکن محققین نے ان روایات کو صحیح تسلیم نہیں کیا کیونکہ جب
دوسری روایات میں یہ صریحا مذکور ہے کہ بنو قینقاع نے اس شرط پر دروازے کھولے تھے کہ ان کی اور ان کے
طبقات ابن سعد جلد ۲ صفحه ۱۹ استثناء باب ۲۰ آیت ۱۲ تا ۱۴ ۳ : طبری صفحه ۱۳۶۱ سطر ۱۴
، ۵: طبری صفحه ۱۳۶۱
زرقانی جلد اصفحہ ۷ ۴۵۸،۴۵
Page 536
۵۲۱
اہل وعیال کی جان بخشی کی جائے گی تو یہ ہر گز نہیں ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول
کر لینے کے بعد دوسرا طریق اختیار فرماتے.البتہ بنو قینقاع کی طرف سے جان بخشی کی شرط کا پیش ہونا
اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھتے تھے کہ ان کی اصل سزا قتل ہی ہے، مگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے رحم کے طالب تھے اور یہ وعدہ لینے کے بعد اپنے قلعے کا دروزاہ کھولنا چاہتے تھے کہ ان کو قتل کی سزا
نہیں دی جاوے گی لیکن گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحیم انفسی سے انہیں معاف کر دیا تھا مگر
معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ اپنی بداعمالی اور جرائم کی وجہ سے اب دنیا کے پردے پر زندہ
چھوڑے جانے کے قابل نہیں تھے.چنانچہ روایت آتی ہے کہ جس جگہ یہ لوگ جلا وطن ہو کر گئے تھے
وہاں انہیں ابھی ایک سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ ان میں کوئی ایسی بیماری وغیرہ پڑی کہ سارے کا سارا
قبیلہ اس کا شکار ہوکر پیوند خاک ہو گیا.غزوہ بنو قینقاع کی تاریخ کے متعلق کسی قدر اختلاف ہے.واقدی اور ابن سعد نے شوال ۲ ہجری
بیان کی ہے اور متاخرین نے زیادہ تر اسی کی اتباع کی ہے، لیکن ابن اسحاق اور ابن ہشام نے اسے غزوہ
سویق کے بعد رکھا ہے جو مسلمہ طور پر ماہ ذی الحجہ ۲ ہجری کے شروع میں ہوا تھا اور حدیث کی ایک روایت
میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ غزوہ بنو قینقاع حضرت فاطمہ کے رخصتانہ کے بعد ہوا تھا کیونکہ اس روایت
میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ولیمہ کی دعوت کا خرچ مہیا کرنے کے لئے یہ تجویز کی تھی کہ
بنو قینقاع کے ایک یہودی زرگر کو ساتھ لے کر جنگل میں جائیں اور وہاں سے اذخر گھاس لا کر مدینہ کے
زرگروں کے پاس فروخت کریں.جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے رخصتانہ کے وقت جو
عام مؤرخین کے نزدیک ذوالحجہ ۲ ہجری میں ہوا تھا ابھی تک بنو قینقاع مدینہ میں ہی تھے.ان وجوہات کی
بنا پر میں نے غزوہ بنو قینقاع کو غزوہ سویق اور حضرت فاطمہ کے رخصتا نہ کے بعد اواخر ۲ ہجری میں
رکھا ہے.واللہ اعلم.اس موقع پر یہ ذکر بھی خالی از فائدہ نہ ہو گا کہ غزوہ بنو قینقاع کا سبب بیان کرتے ہوئے مسٹر مار گولیس
نے اپنی طرف سے ایک عجیب و غریب بات بنا کر لکھی ہے جس کا قطعا کسی روایت میں اشارہ تک
نہیں آتا.بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت حمزہ نے شراب کے نشہ میں (اس وقت تک ابھی
شراب حرام نہیں ہوئی تھی ) حضرت علیؓ کے وہ اونٹ مار دئے تھے جو انہیں جنگ بدر کی غنیمت میں حاصل
زرقانی جلد اصفحه ۴۵۸
بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ بدر
Page 537
۵۲۲
ہوئے تھے.اس منفرد واقعہ کو بغیر کسی قسم کی تاریخی سند کے غزوہ بنو قینقاع کے ساتھ جوڑ کر مسٹر مارگولیس
رقمطراز ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو بیقاع پر اس غرض سے چڑھائی کی تھی کہ تا اس کی
غنیمت سے حضرت علیؓ کے اس نقصان کی تلافی کریں.تاریخ نویسی میں یہ جرات غالبا اپنی مثال آپ ہی
ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ مسٹر مار گولیس اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنی طرف سے قیاس
کر کے زائد کی ہے.دو
چه دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارو
جنت البقیع اور اس کا پہلا مدفون اس سال کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
صحابہ کے لئے مدینہ میں ایک مقبرہ تجویز فرمایا جسے جنت البقیع
کہتے تھے اس کے بعد صحابہ عموماً اس مقبرہ میں دفن ہوتے تھے.سب سے پہلے صحابی جو اس مقبرہ میں دفن
ہوئے تھے وہ عثمان بن مظعون تھے کے عثمان بہت ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے اور نہایت نیک اور عابد
اور صوفی منش آدمی تھے.مسلمان ہونے کے بعد ایک دفعہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
کیا کہ حضور مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تو میں چاہتا ہوں کہ بالکل تارک الدنیا ہوکر اور بیوی بچوں سے
علیحدگی اختیار کر کے اپنی زندگی خالصتہ عبادت الہی کے لئے وقف کر دوں ، مگر آپ نے اس کی اجازت
نہیں دی ہے بلکہ جو لوگ ترک دنیا تو اختیار نہیں کرتے تھے لیکن روزہ اور نماز کی اس قدر کثرت کرتے تھے
کہ اس سے ان کی متعلقین کے حقوق پر اثر پڑتا تھا، ان کے متعلق بھی آپ نے فرمایا کہ تمہیں چاہئے کہ خدا
کا حق خدا کو دو.بیوی بچوں کا حق بیوی بچوں کو دو.مہمان کا حق مہمان کو دو اور اپنے نفس کا حق نفس کو دو
کیونکہ یہ سب حقوق خدا کے مقرر کردہ ہیں اور ان کی ادائیگی عبادت میں داخل ہے.الغرض آپ نے
عثمان بن مظعون کو ترک دنیا کی اجازت نہیں دی.اور اسلام میں تبتل اور رہبانیت کو نا جائز قرار دے کر
اپنی امت کے لئے افراط و تفریط کے درمیان ایک میانہ روی کا راستہ قائم کر دیا.عثمان بن مظعون کی
وفات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور روایت آتی ہے کہ وفات کے بعد آپ نے ان کی
پیشانی پر بوسہ دیا اور اس وقت آپ کی آنکھیں پر نم تھیں.ان کے دفنائے جانے کے بعد آپ نے ان کی
بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ بدر
: اصابه
بخاری کتاب الصوم
: محمد مصنفه مارگولیس صفحه ۲۸۱
بخاری کتاب النکاح
اصابه
Page 538
۵۲۳
قبر کے سرہانے ایک پتھر بطور علامت کے نصب کرادیا اور پھر آپ کبھی کبھی جنت البقیع میں جا کر ان کے
لئے دعا فرمایا کرتے تھے.عثمان پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں فوت ہوئے.غزوہ ذی امر محرم یا صفر ۳ ھ غزوہ قرقرۃ الکدر کے بیان میں یہ ذکر گزر چکا ہے کہ کس طرح قریش
کی انگیخت پر نجد کے قبائل سلیم وغطفان نے مسلمانوں کے خلاف
جارحانہ طریق اختیار کر کے اسلام اور بانی اسلام کو تباہ و برباد کر دینے کا تہیہ کر لیا تھا.ابھی اس واقعہ پر کوئی
زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ بنو غطفان کے بعض قبائل یعنی بنو ثعلبہ اور بنو محارب کے لوگ اپنے ایک
نامور جنگجو دعثور بن حارث کی تحریک پر پھر مدینہ پر اچانک حملہ کر دینے کی نیت سے نجد کے ایک مقام
ذی امر میں جمع ہونے شروع ہوئے.لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی حرکات وسکنات
کا باقاعدہ علم رکھتے تھے آپ کو ان کے اس خونی ارادے کی بروقت اطلاع ہوگئی اور آپ ایک بیدار مغز
جرنیل کی طرح پیش بندی کے طور پر ساڑھے چار سو صحابیوں کی جمعیت کو اپنے ساتھ لے کر تے محرم ۳ھ
کے آخر یا صفر کے شروع میں " مدینہ سے نکلے اور تیزی کے ساتھ کوچ کرتے ہوئے ذی امر کے قریب
پہنچ گئے.دشمن کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے جھٹ پٹ آس پاس کی پہاڑیوں پر چڑھ کر اپنے
آپ کو محفوظ کر لیا اور مسلمان ذی امر میں پہنچے تو میدان خالی تھا.البتہ بنو ثعلبہ کا ایک بدوی جس کا نام
جبار تھا صحابہ کے قابو میں آ گیا.جسے قید کر کے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حالات دریافت کئے تو معلوم ہوا کہ بنو ثعلبہ اور بنو محارب کے
سارے لوگ پہاڑیوں میں محفوظ ہو گئے ہیں اور وہ کھلے میدان میں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئیں گے.ناچار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کا حکم دینا پڑا، مگر اس غزوہ کا اتنا فائدہ ضرور ہو گیا کہ اس وقت جو
خطرہ بنو غطفان کی طرف سے پیدا ہوا تھا.وہ وقتی طور پر ٹل گیا.جبار جو مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوا تھا وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے بخوشی مسلمان ہو گیا اور آپ نے اس کی تربیت کا کام بلال کے سپرد
فرمایا.اور تین دن کے قیام کے بعد آپ مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے.بعض تاریخی روایات کی رو سے اسی غزوہ میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس میں ایک بدوی سردار نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا اور غافل پا کر آپ پر تلوار کے ساتھ حملہ کیا تھا.مگر پھر خود مرعوب ہوکر
ل: اسدالغابہ
۳۲ : ابن سعد
۵ : ابن ہشام وابن سعد : ابن ہشام وابن سعد
ه : ابن ہشام وابن سعد
Page 539
۵۲۴
اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی.لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ بشرطیکہ وہ دو دفعہ نہیں ہوا غزوہ
ذات الرقاع میں پیش آیا تھا جو بروایت صحیح ۷ ہجری میں ہوا تھا.تزویج ام کلثوم ربیع الاول ۲ ہجری رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان بن
عفان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے.ان کی وفات کے بعد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لڑکی ام کلثوم کی شادی جو حضرت فاطمہ سے بڑی مگر رقیہ
سے چھوٹی تھیں حضرت عثمان سے کر دی.اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین دو نوروں والا کہتے ہیں.ام کلثوم کی یہ دوسری شادی تھی کیونکہ وہ اور ان کی بہن رقیہ شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چا
ابولہب کے دولڑکوں سے بیاہی گئیں تھیں.مگر قبل اس کے کہ ان کا رخصتانہ ہوتا مذہبی مخالفت کی بنا پر یہ
رشتہ منقطع ہو گیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عثمان سے رقیہ کی شادی کی اور رقیہ کی وفات
کے بعد ام
کلثوم کی شادی کر دی مگر افسوس ہے کہ ان دونوں صاحبزادیوں کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا کیونکہ
ام کلثوم کے تو کوئی بچہ ہوا ہی نہیں اور رقیہ کا صاحبزادہ عبداللہ چھ سال کا ہو کر وفات پا گیا.ام کلثوم کا
نکاح ربیع الاول ۳ ہجری میں ہوا تھا.غزوہ بحران ربیع الاول ۳ ہجری بنو سلیم اور بنو غطفان کے دوجملوں کی تیاری کا ذکر اوپر گزر چکا
ہے اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی فوری اور بر وقت تدبیر نے خدا کے فضل سے اس وقت مسلمانوں کو ان خونخوار قبائل کے شر سے محفوظ رکھا
تھا.مگر جس کے دل میں عداوت کی آگ سلگ رہی ہو وہ نچلا کس طرح بیٹھ سکتا تھا.ابھی غزوہ ذی امر
پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا یعنی اواخر ربیع الاول ۳ھ میں " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحشتناک اطلاع
موصول ہوئی کہ بنو سلیم پھر موضوع بحران میں مدینہ پر اچانک حملہ کرنے کی غرض سے بہت بڑی تعداد میں
جمع ہورہے ہیں.اور یہ کہ ان کے ساتھ قریش کا بھی ایک جتھہ ہے.ناچار آپ پھر صحابہ کی ایک
جماعت کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے، لیکن حسب عادت عرب کے یہ وحشی درندے جو اپنے شکار
پر اچانک اور غفلت کی حالت میں حملہ کرنے کا موقع چاہتے تھے آپ کی آمد آمد کی خبر پا کر ادھر ادھر منتشر
ا : ابن ہشام وابن سعد
: اصابه واسد الغابه
ه: ابن سعد
بخاری کتاب المغازی باب غزوہ ذات الرقاع
ابن ہشام
ابن ہشام
Page 540
۵۲۵
ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ قیام کر کے واپس تشریف لے آئے.بنوسلیم اور بنو غطفان کا اس طرح بار بار مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے جمع ہونا صاف ظاہر کر رہا
ہے کہ صحرائے عرب کے یہ وحشی اور جنگجو قبائل اسلام کے سخت جانی دشمن تھے اور دن رات اس فکر میں رہتے
تھے کہ کوئی موقع ملے تو مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیں.ذرا مسلمانوں کی اس وقت کی نازک حالت کا اندازہ
لگاؤ کہ ان پر اس زمانہ میں کیسے دن گزر رہے تھے.ایک طرف مکہ کے قریش تھے جن کو اسلام کی عداوت
اور جنگ بدر کی انتقامی روح نے اندھا کر رکھا تھا اور انہوں نے خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لپٹ لپٹ
کر قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ جب تک مسلمانوں
کو ملیا میٹ نہ کریں گے چین نہیں لیں گے.دوسری طرف
صحرائے عرب کے یہ خونخوار درندے تھے جن کو قریش کی انگیخت اور اسلام کی دشمنی نے مسلمانوں کے خون
کی پیاس سے بے چین کر رکھا تھا.چنانچہ دیکھو کہ بدر کے بعد چند ماہ کے اندر اندر آپ کو کتنی دفعہ بذات
خودان وحشی قبائل عرب کے خونی ارادوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے سفر کرنا پڑا اور جیسا کہ
سرولیم میور نے تصریح کی ہے یہ دن بھی بہت سخت گرمیوں کے دن تھے اور گرمی بھی عرب کے صحرا کی گرمی
تھی.اگر خدا کی خاص نصرت شامل حال نہ ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی مسلمانوں
کو ہر وقت ہوشیار اور چوکس نہ رکھتی اور آپ دشمن کی جمعیت کو چھاپہ مارنے سے قبل ہی منتشر کر دینے کی
تدابیر اختیار نہ کرتے تو ان دنوں میں مسلمانوں کی تباہی و بربادی میں کوئی شک نہیں تھا اور یہ صرف بیرونی
خطرات تھے.باقی اندرونی خطرات بھی کسی طرح کم نہ تھے.خود مدینہ کے اندر مسلمانوں سے ملے جلے
رہنے والے منافقین موجود تھے جن کو مار آستین کہنا یقینا کوئی مبالغہ نہیں ہے.ان کے علاوہ غدار اور خفیہ
سازشوں کے عادی یہودی لوگ تھے جن کی عداوت کی گہرائی اور وسعت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی.اللہ اللہ
ان ابتدائی مسلمانوں کے لئے یہ کیسی مصیبت کے دن تھے !! خودان کی زبان سے سنئے.ابی بن کعب ایک
مشہور صحابی روایت کرتے ہیں.كَانُوا لَا يَبِيتُونَ إِلَّا فِى السّلَاحِ وَلَا يُصْبِهُونَ إِلَّا فِيْهِ وَكَانُوا يَقُولُونَ الْاتَرَوْنَ أَنَّا نَعِيْشُ
حَتَّى نَبِيْتُ امِنِينَ مُطْمَئِنِينَ لَانَخَافُ إِلَّا اللَّهَ
یعنی ” اس زمانہ میں صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ ڈر کے مارے راتوں کو ہتھیار لگا لگا کر سوتے
تھے اور دن کو بھی ہر وقت مسلح رہتے تھے کہ کہیں ان پر کوئی اچانک حملہ نہ ہو جاوے اور وہ ایک
حاكم و طبرانی بحواله لباب النقول زیر آیت وعدالله الذين امنوا منكم
Page 541
۵۲۶
دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھئے ہم اس وقت تک زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں کہ جب ہم
امن واطمینان کی زندگی گزاریں گے اور خدا کے سوا ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا.“
ان الفاظ میں کس مصیبت اور کس بے کسی کا اظہار ہے اور امن اور اطمینان کی زندگی کی کتنی تڑپ مخفی
ہے.اس کا اندازہ ہر انصاف پسند شخص خود کرسکتا ہے.سریہ زید بن حارثہ بطرف قردہ جمادی الآخرۃ ۳ ہجری بنوسلیم اور بنو غطفان کے حملوں سے
کچھ فرصت ملی تو مسلمانوں کو ایک
اور خطرہ کے سدباب کے لئے وطن سے نکلنا پڑا.اب تک قریش اپنی شمالی تجارت کے لئے عموماً حجاز کے
ساحلی راستے سے شام کی طرف جاتے تھے لیکن اب انہوں نے یہ راستہ ترک کر دیا کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان
کیا جا چکا ہے اس علاقہ کے قبائل مسلمانوں کے حلیف بن چکے تھے اور قریش کے لئے شرارت کا موقع کم تھا
بلکہ ایسے حالات میں وہ اس ساحلی راستے کو خود اپنے لئے موجب خطرہ سمجھتے تھے.بہر حال اب انہوں نے
اس راستے کو ترک کر کے نجدی راستہ اختیار کر لیا جو عراق کو جاتا تھا اور جس کے آس پاس قریش کے حلیف
اور مسلمانوں کے جانی دشمن قبائل سلیم و غطفان آباد تھے.چنانچہ جمادی الآخرۃ کے مہینہ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ نجدی راستہ سے گزرنے والا
ہے.ظاہر ہے کہ اگر قریش کے قافلوں کا ساحلی راستے سے گزرنا مسلمانوں کے لئے موجب خطرہ تھا تو
نجدی راستے سے ان کا گزرنا ویسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اندیشہ ناک تھا کیونکہ بر خلاف ساحلی راستے کے
اس راستے پر قریش کے حلیف آباد تھے جو قریش ہی کی طرح مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور جن کے
ساتھ مل کر قریش بڑی آسانی کے ساتھ مدینہ پر خفیہ چھاپہ مار سکتے یا کوئی شرارت کر سکتے تھے اور پھر قریش
کو کمزور کرنے اور انہیں صلح جوئی کی طرف مائل کرنے کی غرض کے ماتحت بھی ضروری تھا کہ اس راستہ پر بھی
ان کے قافلوں کی روک تھام کی جاوے.اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے ملتے ہی اپنے
آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی سرداری میں اپنے اصحاب کا ایک دستہ روانہ فرما دیا.قریش کے اس تجارتی قافلے میں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کے جیسے رؤساء بھی موجود
تھے.زید نے نہایت چستی اور ہوشیاری سے اپنے فرض کو ادا کیا اور نجد کے مقام قردہ میں ان دشمنان اسلام
کو جاد با یا.اس اچانک حملہ سے گھبرا کر قریش کے لوگ قافلہ کے اموال و امتعہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور زید
ا ابن ہشام
ابن ہشام
: ابن سعد
Page 542
۵۲۷
بن حارثہ اور ان کے ساتھی ایک کثیر مال غنیمت کے ساتھ مدینہ میں بانیل ومرام واپس آگئے.بعض
مؤرخین نے لکھا ہے کہ قریش کے اس قافلہ کا راہبر ایک فرات نامی شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ قید
ہوا اور مسلمان ہونے پر رہا کر دیا گیا.لیکن دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف
مشرکین کا جاسوس تھا، مگر بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر کے آ گیا.قتل کعب بن اشرف جمادی الآخرة ۳ ہجری بدر کی جنگ نے جس طرح مدینہ کے یہودیوں
کی دلی عداوت کو ظاہر کر دیا تھا اس کا ذکر غزوہ
بنو قینقاع کے بیان میں گزر چکا ہے، مگر افسوس ہے کہ بنو قینقاع کی جلا وطنی بھی دوسرے یہودیوں کو اصلاح
کی طرف مائل نہ کر سکی اور وہ اپنی شرارتوں اور فتنہ پردازیوں میں ترقی کرتے گئے.چنانچہ کعب بن اشرف
کے قتل کا واقعہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے.کعب گوند ہبا یہودی تھا لیکن دراصل یہودی النسل نہ تھا بلکہ
عرب تھا.اس کا باپ اشرف بنو مہان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزہ آدمی تھا جس نے مدینہ میں آکر بنو نضیر
کے ساتھ تعلقات پیدا کئے اور ان کا حلیف بن گیا اور بالآخر اس نے اتنا اقتدار اور رسوخ پیدا کرلیا کہ قبیلہ
بنونضیر کے رئیس اعظم ابورافع بن ابی الحقیق نے اپنی لڑکی اسے رشتہ میں دے دی.اسی لڑکی کے بطن سے
کعب پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر رتبہ حاصل کیا.حتی کہ بالآخر ا سے یہ حیثیت
حاصل ہوگئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے گویا اپنا سر دار سمجھنے لگ گئے.کعب ایک وجیہ اور شکیل شخص ہونے کے
علاوہ ایک قادر الکلام شاعر اور ایک نہایت دولتمند آدمی تھا اور ہمیشہ اپنی قوم کے علماء اور دوسرے ذی اثر
لوگوں کو اپنی مالی فیاضی سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا تھائے مگر اخلاقی نقطہ نگاہ سے وہ ایک نہایت گندے
اخلاق کا آدمی تھا اور خفیہ چالوں اور ریشہ دوانیوں کے فن میں اسے کمال حاصل تھا.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو کعب بن اشرف نے
دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر اس معاہدہ میں شرکت اختیار کی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود
کے درمیان باہمی دوستی اور امن و امان اور مشتر کہ دفاع کے متعلق تحریر کیا گیا تھا.مگر اندر ہی اندر کعب
کے دل میں بغض و عداوت کی آگ سلگنے لگ گئی اور اس نے خفیہ چالوں اور مخفی ساز باز سے اسلام اور
بانی اسلام کی مخالفت شروع کر دی.چنانچہ لکھا ہے کہ کعب ہر سال یہودی علماء ومشائخ کو بہت سی خیرات
ابن سعد
زرقانی
: اصابه واستيعاب
۵: زرقانی جلد ۲ صفحه ۹
ابن ہشام
Page 543
۵۲۸
دیا کرتا تھا لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ لوگ اپنے سالانہ وظائف لینے کے
لئے اس کے پاس گئے تو اس نے باتوں باتوں میں ان کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع
کر دیا اور ان سے آپ کے متعلق مذہبی کتب کی بنا پر رائے دریافت کی.انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہ وہی نبی
معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا.کعب اس جواب پر بہت بگڑا اور ان کو سخت سست کہہ کر وہاں
سے رخصت کر دیا.اور جو خیرات انہیں دیا کرتا وہ نہ دی.یہودی علماء کی جب روزی بند ہوئی تو کچھ عرصہ
کے بعد پھر کعب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں علامات کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی تھی ہم نے دوبارہ غور کیا ہے
در اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا.اس جواب سے کعب کا مطلب حل ہو گیا
اور اس نے خوش ہو کر ان کو سالانہ خیرات دے دی.خیر یہ تو ایک مذہبی مخالفت تھی جو گونا گوار صورت میں
اختیار کی گئی لیکن چنداں قابل اعتراض نہیں ہو سکتی تھی اور نہ اس بنا پر کعب کو زیر الزام سمجھا جاسکتا تھا، مگر اس
کے بعد کعب کی مخالفت زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتی گئی اور بالآخر جنگ بدر کے بعد تو اس نے ایسا
رویہ اختیار کیا جو سخت مفسدانہ اور فتنہ انگیز تھا.اور جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے لئے نہایت خطرناک
حالات پیدا ہو گئے.در اصل بدر سے پہلے کعب یہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں
کا یہ جوش ایمان ایک عارضی چیز ہے
اور آہستہ آہستہ یہ سب لوگ خود بخود منتشر ہو کر اپنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ جائیں گے لیکن جب بدر
کے موقع پر مسلمانوں کو ایک غیر معمولی فتح نصیب ہوئی اور رؤساء قریش اکثر مارے گئے تو اس نے سمجھ لیا
کہ اب یہ نیا دین یو نہی مئتا نظر نہیں آتا.چنانچہ بدر کے بعد اس نے اپنی پوری کوشش اسلام کے مٹانے
اور تباہ و برباد کر نے میں صرف کر دینے کا تہیہ کر لیا.اس کے دلی بغض وحسد کا سب سے پہلا اظہار اس
موقع پر ہوا جبکہ بدر کی فتح کی خبر مدینہ میں پہنچی.اس خبر کو سن کر کعب نے علی رؤس الا شہاد یہ کہا کہ یہ خبر
بالکل جھوٹی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ مکن نہیں کہ محمدصلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ایسے بڑے لشکر پر فتح حاصل
ہوا اور مکہ کے اتنے نامور رئیس خاک میں مل جائیں اور اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر اس زندگی سے مرنا بہتر ہے.جب اس خبر کی تصدیق ہوگئی اور کعب کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعی بدر کی فتح نے اسلام کو وہ استحکام دے دیا
ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا تو وہ غیض و غضب سے بھر گیا اور فور أسفر کی تیاری کر کے اس نے مکہ
کی راہ لی اور وہاں جا کر اپنی چرب زبانی اور شعر گوئی کے زور سے قریش کے دلوں کی سلگتی ہوئی آگ کو
شعلہ بار کر دیا اور ان کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ سمجھنے والی پیاس پیدا کر دی اور ان کے سینے
زرقانی جلد ۲ صفحه ۸
: ابن ہشام وابن سعد
Page 544
۵۲۹
جذبات انتقام وعداوت سے بھر دئے.اور جب کعب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں
ایک انتہائی درجہ کی بجلی پیدا ہو گئی تو اس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر اور کعبہ کے پردے
ان کے ہاتھوں میں دے دے کر ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کو صفحہ نیا سے
ملیا میٹ نہ کر دیں گے ، اس وقت تک چین نہ لیں گے.مکہ میں یہ آتش فشاں فضا پیدا کر کے اس بد بخت
نے دوسرے قبائل عرب کا رخ کیا اور قوم بقوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑ کا یا.اور پھر
مدینہ میں واپس آکر مسلمان خواتین پر تشبیب کہی.یعنی اپنے جوش دلانے والے اشعار میں نہایت گندے
اور مخش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا ہے حتی کہ خاندان نبوت کی مستورات کو بھی اپنے ان او باشانہ
اشعار کا نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کیا.اور ملک میں ان اشعار کا چرچا کروایا.اور بالآخر اس نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان
پر بلا کر چندنو جوان یہودیوں سے آپ
کو قتل کروانے کا منصو بہ باندھا.مگر خدا کے فضل سے وقت پر اطلاع
ہو گئی اور اس کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی.جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور کعب کے خلاف عہد شکنی، بغاوت ،تحریک جنگ فتنہ پردازی ،مخش
گوئی اور سازش قتل کے الزامات پایہ ثبوت کو پہنچ گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بین الاقوام
معاہدہ کی رو سے جو آپ کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اہالیان مدینہ میں ہوا تھ مدینہ کی جمہوری سلطنت
کے صدر اور حاکم اعلیٰ تھے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ کعب بن اشرف اپنی کاروائیوں کی وجہ سے واجب القتل
ہے اور اپنے بعض صحابیوں کو ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جا وے.لیکن چونکہ اس وقت کعب کی
فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مدینہ کی فضا ایسی ہو رہی تھی کہ اگر اس کے خلاف باضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے
قتل کیا جاتا تو مدینہ میں ایک خطرناک خانہ جنگی شروع ہو جانے کا احتمال تھا.جس میں نہ معلوم کتنا
کشت وخون ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرممکن اور جائز قربانی کر کے بین الاقوام کشت و خون کو روکنا
چاہتے تھے.آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ کعب کو بر ملا طور پر قتل نہ کیا جاوے بلکہ چند لوگ خاموشی کے ساتھ
: فتح الباری جلد ے صفحہ ۲۵۹
ا ابو داؤ د کتاب الخراج نیز ابن ہشام وابن سعد
زرقانی جلد ۲ صفحه ۹
خمیس جلد اصفحه ۴ ۴۷ و زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۰
: ابن ہشام ۵ : طبری والروض الانف
کے ابوداؤ د کتاب الخراج نیز بخاری باب قتل کعب بن اشرف
Page 545
۵۳۰
کوئی مناسب موقع نکال کر اسے قتل کر دیں اور یہ ڈیوٹی آپ نے قبیلہ اوس کے ایک مخلص صحابی محمد بن مسلمہ
کے سپر دفرمائی اور انہیں تاکید فرمائی کہ جو طریق بھی اختیار کریں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کے مشورہ
سے کریں یا محمد بن مسلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خاموشی کے ساتھ قتل کرنے کے لئے تو کوئی بات
کہنی ہوگی.یعنی کوئی عذر وغیرہ بنانا پڑے گا جس کی مدد سے کعب کو اس کے گھر سے نکال کر کسی محفوظ جگہ
میں قتل کیا جا سکے.آپ نے ان عظیم الشان اثرات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو اس موقع پر ایک خاموش سزا کے
طریق کو چھوڑنے سے پیدا ہو سکتے تھے فرمایا ” اچھا.چنانچہ محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشورہ سے
ابونا ئلہ اور دو تین اور صحابیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے اور کعب کو اس کے اندرون خانہ
سے بلا کر کہا کہ ” ہمارے صاحب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگتے ہیں اور ہم تنگ
حال ہیں.کیا تم مہربانی کر کے ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو؟ یہ بات سن کر کعب خوشی سے کود پڑا اور کہنے
لگا.واللہ ابھی کیا ہے، وہ دن دور نہیں جب تم اس شخص سے بیزار ہوکر اسے چھوڑ دو گے.محمد نے جواب
دیا.خیر ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر چکے ہیں اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلہ کا
انجام کیا ہوتا ہے.مگر تم یہ بتاؤ کہ قرض دو گے یا نہیں ؟ کعب نے کہا ”ہاں ! مگر کوئی چیز رہن رکھو.“ محمد نے
پوچھا کیا چیز ؟ اس بدبخت نے جواب دیا.” اپنی عورتیں رہن رکھ دو.محمد نے غصہ کو دبا کر کہا کہ یہ کیسے
ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیسے آدمی کے پاس ہم اپنی عورتیں رہن رکھ دیں.اس نے کہا اچھا تو پھر بیٹے سہی.محمد
نے جواب دیا کہ یہ بھی ناممکن ہے.ہم سارے عرب کا طعن اپنے سر پر نہیں لے سکتے ، البتہ اگر تم مہربانی
کرو تو ہم اپنے ہتھیار رہن رکھ دیتے ہیں.کعب راضی ہو گیا اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی رات کو آنے
کا وعدہ دے کر واپس چلے آئے.جب رات ہوئی تو یہ پارٹی ہتھیار وغیرہ ساتھ لے کر ( کیونکہ اب وہ
بر ملا طور پر ہتھیار اپنے ساتھ لے جاسکتے تھے ) کعب کے مکان پر پہنچے اور اسے اس کے گھر سے نکال کر
باتیں کرتے کرتے ایک طرف کو لے آئے.تھوڑی دیر بعد چلتے چلتے محمد بن مسلمہ یا ان کے کسی ساتھی نے
کسی بہانے سے کعب کے سر پر ہاتھ ڈالا اور نہایت پھرتی کے ساتھ اس کے بالوں کو مضبوطی سے قابو کر کے
زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۰
ہے : یہ بات گو اس موقع کے لئے اختیار کی گئی ہو مگر اپنی جگہ درست تھی کیونکہ واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
صحابیوں سے قومی ضروریات کے لئے چندے اور زکوۃ کا مطالبہ فرمایا کرتے تھے اور یہ بھی درست ہے کہ صحابہ عمو مانا دار
اور غریب تھے.
Page 546
۵۳۱
اپنے ساتھیوں کو آواز دی مارو صحابہ نے جو پہلے سے تیار اور ہتھیار بند تھے فوراً تلوار میں چلا دیں اور
بالآخر کعب قتل ہو کر گرا.اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی وہاں سے رخصت ہوکر جلدی جلدی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ کو اس قتل کی اطلاع دی.جب کعب کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی اور یہودی لوگ سخت جوش میں آگئے
اور دوسرے دن صبح کے وقت یہودیوں کا ایک وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور
شکایت کی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف اس اس طرح قتل کر دیا گیا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی باتیں سن کر فر مایا کہ کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کعب کس کس جرم کا مرتکب ہوا ہے اور پھر آپ نے
اجمالاًان کو کعب کی عہد شکنی اور تحریک جنگ اور فتنہ انگیزی اور بخش گوئی اور سازش قتل وغیرہ کی کارروائیاں
یاد دلائیں تے جس پر یہ لوگ ڈر کر خاموش ہو گئے." اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فرمایا کہ تمہیں چاہئے کہ کم از کم آئندہ کے لئے ہی امن اور تعاون کے ساتھ رہو اور عداوت اور فتنہ وفساد
کا بیج نہ بوؤ.چنانچہ یہود کی رضامندی کے ساتھ آئندہ کے لئے ایک نیا معاہدہ لکھا گیا اور یہود نے
مسلمانوں کے ساتھ امن وامان کے ساتھ رہنے اور فتنہ و فساد کے طریقوں سے بچنے کا از سرنو وعدہ کیا."
اور یہ عہد نامہ حضرت علی کی سپردگی میں دے دیا گیا.اور تاریخ میں کسی جگہ مذکور نہیں کہ اس کے بعد
یہودیوں نے کبھی کعب بن اشرف کے قتل کا ذکر کر کے مسلمانوں پر الزام قائم کیا ہو کیونکہ ان کے دل محسوس
کرتے تھے کہ کعب اپنی مستحق سزا کو پہنچا ہے.کعب بن اشرف کے قتل پر بعض مغربی مؤرخین نے بڑی خامہ فرسائی کی ہے اور اس واقعہ کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر ایک بدنما دھبے کے طور پر ظاہر کر کے اعتراضات جمائے ہیں لیکن دیکھنا یہ
ہے کہ اول آیا یقتل فی ذاتہ ایک جائز فعل تھا یا نہیں؟ دوسرے آیا جوطریق اس قتل کے واسطے اختیار کیا گیا
وہ جائز تھایا نہیں ؟ امراوّل کے متعلق تو یہ یا درکھنا چاہئے کہ کعب بن اشرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ باقاعدہ امن وامان کا معاہدہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا تو درکنار رہا اس نے
اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ ہر بیرونی دشمن کے خلاف مسلمانوں کی امداد کرے گا اور مسلمانوں کے ساتھ
بخاری باب قتل کعب بن اشرف
فتح الباری جلد ۷ صفحه ۲۶۲ و زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۴
ابوداؤ د کتاب الخراج و نیز ابن سعد
ابوداؤ د كتاب الخراج باب كيف كان اخراج اليهود ونيز ابن سعد ۵ : ابن سعد
Page 547
۵۳۲
دوستانہ تعلقات رکھے گا.اس نے اس معاہدہ کی رو سے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ جو رنگ مدینہ میں جمہوری
سلطنت کا قائم کیا گیا ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہوں گے اور ہر قسم کے تنازعات وغیرہ
میں آپ کا فیصلہ سب کے لئے واجب القبول ہوگا.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسی معاہدہ کے ماتحت
یہودی لوگ اپنے مقدمات وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور آپ ان
میں احکام جاری فرماتے تھے.چنانچہ آپ نے ایک زنا کے مقدمہ میں ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کو
تورات کے حکم کے مطابق رجم کی سزادی تھی.اب اگر ان حالات کے ہوتے ہوئے کعب نے تمام
عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں سے بلکہ حق یہ ہے کہ حکومت وقت سے غداری کی اور مدینہ میں
فتنہ وفساد کا بیج بویا اور ملک میں جنگ کی آگ مشتعل کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب
کو خطرناک طور پر ابھارا اور مسلمانوں کی عورتوں پر اپنے جوش دلانے والے اشعار میں تشبیب کہی اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کئے.اور یہ سب کچھ ایسی حالت میں کیا کہ مسلمان پہلے
سے ہی چاروں طرف سے مصائب میں گھرے ہوئے تھے اور عرب کے خونخوار درندے ان کے خون کی
پیاس میں مجنون ہورہے تھے اور صحابہ کی ایسی حالت تھی کہ نہ دن آرام میں گزرتا تھا اور نہ رات اور دشمن
کے حملہ کے خطرہ میں ان کی نیند تک حرام ہو رہی تھی.تو کیا ان حالات میں کعب کا جرم بلکہ بہت سے
جرموں کا مجموعہ ایسا نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی تعزیری قدم اٹھایا جاتا ؟ اور پھر کیا قتل سے کم کوئی اور سزا
تھی جو یہود کی اس فتنہ پردازی کے سلسلہ کو روک سکتی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غیر متعصب شخص کعب کے قتل کو
ایک غیر منصفانہ فعل سمجھ سکتا ہے.کیا آج کل مہذب کہلانے والے ممالک میں بغاوت اور عہد شکنی اور
اشتعال جنگ اور سازش قتل کے جرموں میں مجرم کو قتل کی سزا نہیں دی جاتی ؟
دوسرا سوال قتل کے طریق سے تعلق رکھتا ہے.سو اس کے متعلق یا درکھنا چاہئے کہ عرب میں اس وقت
!
کوئی باقاعدہ سلطنت نہ تھی، بلکہ ہر شخص اور ہر قبیلہ آزاد اورخود مختار تھا.ایسی صورت میں وہ کون سی عدالت
تھی جہاں کعب کے خلاف مقدمہ دائر کر کے باقاعدہ قتل کا حکم حاصل کیا جاتا ؟ کیا یہود کے پاس اس کی
شکایت کی جاتی جن کا وہ سردار تھا اور جو خود مسلمانوں کے خلاف غداری کر چکے تھے اور آئے دن فتنے
کھڑے کرتے رہتے تھے؟ کیا مکہ کے قریش کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا جو مسلمانوں کے خون کے
پیاسے تھے؟ کیا قبائل سلیم و غطفان سے دادرسی چاہی جاتی جو گزشتہ چند ماہ میں تین چار دفعہ مدینہ پر چھاپہ
بخاری کتاب المحاربین
Page 548
۵۳۳
مارنے کی تیاری کر چکے تھے ؟ اس وقت کی عرب کی حالت پر غور کرو اور پھر سوچو کہ مسلمانوں کے لئے
سوائے اس کے وہ کون سا راستہ کھلا تھا کہ جب ایک شخص کی اشتعال انگیزی اور تحریک جنگ اور فتنہ پردازی
اور سازش قتل کی وجہ سے اس کی زندگی کو اپنے لئے اور ملک کے امن کے لئے خطرناک پاتے تو خود حفاظتی
کے خیال سے موقع پا کر اسے خود قتل کر دیتے کیونکہ یہ بہت بہتر ہے کہ ایک شریر اور مفسد آدمی قتل ہو جاوے
بجائے اس کے کہ بہت سے پر امن شہریوں کی جان خطرے میں پڑے اور ملک کا امن برباد ہو.پھر جیسا
کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ اس معاہدہ کی رو سے جو ہجرت کے بعد مسلمانوں
اور یہود کے درمیان ہوا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی شہری کی حیثیت حاصل نہ تھی، بلکہ
آپ اس جمہوری سلطنت کے صدر قرار پائے تھے جو مدینہ میں قائم ہوئی تھی.اور آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا
کہ جملہ تنازعات اور امور سیاسی جو فیصلہ مناسب خیال کریں صادر فرمائیں.پس اگر آپ نے ملک کے
امن کے مفاد میں کعب کی فتنہ پردازی کی وجہ سے اسے واجب القتل قرار دیا تو آج تیرہ سوسال گزرنے پر
جبکہ اس زمانہ کے بہت سے تفصیلی حالات بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ
آپ کے فیصلہ پر عدالت اپیل بن کر بیٹھے.خصوصاً جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ خود یہود نے کعب کی اس
سزا کو اس کے جرموں کی روشنی میں واجبی سمجھ کر خاموشی اختیار کی اور اس پر اعتراض نہیں کیا اور اگر یہ
اعتراض کیا جاوے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ قتل کا حکم دینے سے پہلے یہود کو بلا کر ان کو کعب کے یہ جرم
سنائے جاتے اور حجت پوری کرنے کے بعد اس کے قتل کا باقاعدہ اور برملاطور پر حکم دیا جاتا، تو اس کا جواب
اوپر گزر چکا ہے کہ اس وقت حالات ایسے نازک ہورہے تھے کہ ایسا طریق اختیار کرنے سے بین الاقوام
پیچیدگیوں کے بڑھنے کا سخت خطرہ تھا اور کوئی تعجب نہ تھا کہ مدینہ میں ایک خطرناک سلسلہ کشت وخون
اور خانہ جنگی کا شروع ہو جاتا.پس ان کاموں کی طرح جو جلد اور خاموشی کے ساتھ ہی کر گزرنے سے
فائدہ مند ہوتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عامہ کے خیال سے یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی
کے ساتھ کعب کی سزا کا حکم جاری کر دیا جاوے مگر اس میں قطعاً کسی قسم کے دھو کے کا دخل نہ تھا اور نہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشاء تھا کہ یہ سزا ہمیشہ کے لئے بصیغہ راز رہے کیونکہ جونہی یہود کا وفد
دوسرے دن صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فوراً بلا توقف انہیں ساری سرگزشت سنا دی اور
اس فعل کی پوری پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے کر یہ ثابت کر دیا کہ اس میں کوئی دھو کے وغیرہ کا سوال نہیں
ابن ہشام
Page 549
۵۳۴
ہے اور یہودیوں کو یہ بات واضح طور پر بتادی کہ فلاں فلاں خطرناک جرموں کی بنا پر کعب کے متعلق یہ سزا
تجویز کی گئی تھی جو میرے حکم سے جاری کی گئی ہے.اس وفد نے آپ کے اس بیان کی معقولیت کو تسلیم کیا
اور کعب کے جرموں کو اس کی سزا کا کافی اور جائز باعث یقین کرتے ہوئے خاموش ہو گئے.باقی رہا یہ اعتراض کہ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جھوٹ اور فریب کی
اجازت دی.سو یہ بالکل غلط ہے اور صحیح روایات اس کی مکذب ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
قطعاً جھوٹ اور غلط بیانی کی اجازت نہیں دی بلکہ صحیح بخاری کی روایت کے بموجب جو اصح الروایات ہے
جب محمد بن مسلمہ نے آپ سے یہ دریافت کیا کہ کعب کو خاموشی کے ساتھ قتل کرنے کے لئے تو کوئی بات
کہنی پڑے گی تو آپ نے ان عظیم الشان فوائد کوملحوظ رکھتے ہوئے جو خاموش سزا کے محرک تھے جواب میں
صرف اس قدر فر مایا کہ ”ہاں“ اور اس سے زیادہ اس موقع پر آپ کی طرف سے یا محمد بن مسلمہ کی طرف سے
قطعا کوئی تشریح یا توضیح نہیں ہوئی.اور ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ
محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھی جو کعب کے مکان پر جا کر اسے باہر نکال کر لائیں گے تو اس موقع پر انہیں
لازماً کوئی ایسی بات کہنی ہوگی جس کے نتیجہ میں کعب رضامندی اور خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل کر ان کے
ساتھ آجاوے اور اس میں ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے.آخر جنگ کے دوران میں جاسوس وغیرہ جو اپنے
فرائض ادا کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی قسم کی باتیں کہنی ہی پڑتی ہے جس پر کبھی کسی عقل مند کو اعتراض نہیں
ہوا.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تو بہر حال پاک ہے.باقی رہا محمد بن مسلمہ وغیرہ کا معاملہ
جنہوں نے وہاں جا کر عملاً اس قسم کی باتیں کیں.سوان کی گفتگو میں بھی درحقیقت کوئی بات خلاف اخلاق
نہیں ہے.انہوں نے حقیقتا کوئی غلط بیانی نہیں کی.البتہ اپنے مشن کی غرض وغایت کو مدنظر رکھتے ہوئے
کچھ ذو معنیین الفاظ ضرور کہے مگر ان کے بغیر چارہ نہیں تھا اور حالات جنگ میں ایک اچھی اور نیک غرض
کے ماتحت سادہ اور صاف گوئی کے طریق سے اس قدر مخفی انحراف ہرگز کسی عقل مند دیانت دار شخص کے
نزدیک قابل اعتراض نہیں ہو سکتا بلکہ حق یہ ہے کہ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں کی یہ گفتگو اس نیک اثر
کی ایک بہت عمدہ اور دلچسپ دلیل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے آپ کے صحابہ پر پیدا کیا
تھا.عرب کے لوگوں کی اسلام سے قبل کیا حالت تھی؟ کیا اس میں کوئی شک ہے کہ وہ ہر قسم کے گندوں میں
مبتلا تھے اور دھوکہ فریب جھوٹ تو گویا ان کی فطرت کا حصہ بن چکا تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
بخاری باب قتل کعب بن اشرف
Page 550
۵۳۵
قلیل صحبت نے ان کے قلوب پر اس قدر گہرا اثر پیدا کیا کہ جھوٹ بولنا تو در کنار رہا وہ ایک نہایت اچھی
اور نیک غرض کے ماتحت بھی سادہ اور صاف گوئی کے طریق سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے
تھے.چنانچہ اس خطرناک موقع پر بھی جو کعب بن اشرف کی شرانگیزی نے پیدا کر دیا تھا ان کو صاف گوئی
کے راستے سے ایک نہایت خفی انحراف کرنے کے لئے بھی اپنے آقا کی اجازت کی ضرورت محسوس ہوئی.ان کے اس نمونے کے مقابلہ میں اگر یہ دیکھا جاوے کہ آج کل دنیا میں ہر قوم وملت میں اس جھوٹے
اصول کے ماتحت کہ ایک نیک غرض کے لئے ہر کام کرنا جائز ہے کیا کچھ ظلم ڈھایا جاتا اور کیسے مظالم
اور اکاذیب روار کھے جاتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک
اور معجزہ نما اثر کی دل سے تعریف نکلتی ہے جو آپ کی تربیت نے عرب کے جاہل اور وحشی لوگوں میں ایسے
قلیل عرصہ میں پیدا کیا.کیا جنگ میں جھوٹ بولنا اور دھوکا دینا جائز ہے
بعض روایتوں میں یہ مذکور ہوا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے
تھے کہ الْحَرْبُ خُدُعَةٌ یعنی ” جنگ تو ایک دھوکا ہے.“ اور اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ میں دھوکے کی اجازت تھی.حالانکہ اول تو الْحَرُبُ
خُدعة کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جنگ میں دھوکا کرنا جائز ہے بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ ” جنگ خود
ایک دھوکا ہے.یعنی جنگ کے نتیجہ کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا.یعنی جنگ کے نتیجہ پر اتنی
مختلف با تیں اثر ڈالتی ہیں کہ خواہ کیسے ہی حالات ہوں نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور ان معنوں کی
تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ حدیث میں یہ روایت دو طرح سے مروی ہوئی ہے.ایک روایت میں یہ
الفاظ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْحَرْبُ خُدَعَةٌ یعنی ” جنگ ایک دھوکا ہے اور دوسری
روایت میں یہ ہے کہ سَمَّى الْحَرْبُ خُدْعَةٌ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا نام دھوکا رکھا
تھا اور دونوں کے ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ
کا منشایہ نہیں تھا کہ جنگ میں دھوکا کرنا جائز ہے بلکہ یہ
تھا کہ جنگ خود ایک دھوکا دینے والی چیز ہے لیکن اگر ضرور اس کے یہی معنی کئے جائیں کہ جنگ میں دھوکا
جائز ہے تو پھر بھی یقیناً اس جگہ دھو کے سے جنگی تدبیر اور حیلہ مراد ہے جھوٹ اور فریب ہرگز مراد نہیں ہے
کیونکہ اس جگہ خُدعة کے معنے داؤ پیچ اور تدبیر جنگ کے ہیں جھوٹ اور فریب کے نہیں ہیں.پس مطلب
: بخارى كتاب الجهاد باب الْحَرْبُ خُدْعَةٌ
Page 551
۵۳۶
یہ ہے کہ جنگ میں اپنے دشمن کو کسی حیلہ اور تدبیر سے غافل کر کے قابو میں لے آنا یا مغلوب کر لینا منع نہیں
ہے اور اس قسم کے داؤ پیچ کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں.مثلا صیح روایات سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم جب کسی مہم میں نکلتے تھے تو عموماً اپنا منزل مقصود ظاہر نہیں فرماتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی
کرتے تھے کہ جانا تو جنوب کی طرف ہوتا تھا، مگر شروع شروع میں شمال کی طرف رخ کر کے روانہ
ہو جاتے تھے اور پھر چکر کاٹ کر جنوب کی طرف گھوم جاتے تھے یا جب
کبھی کوئی شخص پوچھتا تھا کہ کدھر سے
آئے ہو تو بجائے مدینہ کا نام لینے کے قریب یا دور کے پڑاؤ کا نام لے دیتے تھے یا اسی قسم کی کوئی اور جائز
جنگی تدبیر اختیار فرماتے تھے یا جیسا کہ قرآن شریف میں اشارہ کیا گیا ہے صحابہ بعض اوقات ایسا کرتے
تھے کہ دشمن کو غافل کرنے کے لئے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے تھے اور جب دشمن غافل
ہو جا تا تھا اور اس کی صفوں میں ابتری پیدا ہو جاتی تھی تو پھر اچانک حملہ کر دیتے تھے اور یہ ساری صورتیں
اس خُدعة کی ہیں جسے حالات جنگ میں جائز قرار دیا گیا ہے اور اب بھی جائز سمجھا جاتا ہے ، لیکن یہ کہ
جھوٹ اور غداری وغیرہ سے کام لیا جاوے اس سے اسلام نہایت سختی کے ساتھ منع کرتا ہے چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں خدا کے ساتھ شرک کرنے اور والدین کے حقوق تلف
کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر جھوٹ بولنے کا گناہ سب سے بڑا ہے.نیز فرماتے تھے کہ ایمان
166
اور بزدلی ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں مگر ایمان اور جھوٹ کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے." اور دھو کے
اور غداری کے متعلق فرماتے تھے کہ جو شخص غداری کرتا ہے وہ قیامت کے دن خدا کے سخت عتاب کے نیچے
ہوگا.الغرض جنگ میں جس قسم کے خُدعة کی اجازت دی گئی ہے وہ حقیقی دھوکا یا جھوٹ نہیں ہے بلکہ
اس سے وہ جنگی تدابیر مراد ہیں جو جنگ میں دشمن کو غافل کرنے یا اسے مغلوب کرنے کے لئے اختیار کی
جاتی ہیں اور جو بعض صورتوں میں ظاہری طور پر جھوٹ اور دھو کے کے مشابہ تو سمجھی جاسکتی ہیں مگر وہ حقیقتاً
جھوٹ نہیں ہوتیں.چنانچہ مندرجہ ذیل حدیث ہمارے اس خیال کی مصدق ہے..عَنْ أُمِّ كُلْتُوْمَ بِنْتِ عَقَبَةَ بْنِ أَبِى مُعِيطٍ قَالَتْ لَمُ اَسْمَعِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
يُرَخّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كِذَبْ إِلَّا فِى ثَلَاثِ الْحَرْبِ وَالْإِ صَلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا
مسلم کتاب الایمان موطا امام مالک باب ماجاء فی الصدق والكذب آخر الكتاب
: مسلم كتاب الجهاد باب تحريم الغدر مسلم بحوالہ مشکوۃ باب ماينهى من التهاجر
Page 552
۵۳۷
یعنی ام کلثوم بنت عقبہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو صرف
تین موقعوں کے لئے ایسی باتوں کی اجازت دیتے سنا جو حقیقتا تو جھوٹ نہیں ہوتیں مگر عام
لوگ انہیں غلطی سے جھوٹ
سمجھ سکتے ہیں.اول جنگ.دوم لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان
66
صلح کرانے کا موقع اور سوم جبکہ مرد اپنی عورت سے یا عورت اپنے مرد سے کوئی ایسی بات
کرے جس میں ایک دوسرے کو راضی اور خوش کرنا مقصود ہو.یہ حدیث اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ جس قسم کے خُدعة کی جنگ میں اجازت
دی گئی ہے، اس سے جھوٹ اور دھو کا مراد نہیں ہے بلکہ وہ باتیں مراد ہیں جو بعض اوقات جنگی تدابیر کے
طور پر اختیار کرنی ضروری ہوتی ہیں اور جو ہر قوم اور ہر مذہب میں جائز سمجھی گئی ہیں.کعب بن اشرف کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ابن ہشام نے یہ روایت نقل کی ہے کہ کعب کے قتل کے
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب جس یہودی پر تم قابو پاؤ سے قتل
کرد و.چنانچہ ایک صحابی محیصہ نامی نے ایک یہودی پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا تھا اور یہی روایت ابو داؤد
نے نقل کی ہے اور دونوں روایتوں کا منبع ابن اسحاق ہے.علم روایت کی رو سے یہ روایت کمزور اور نا قابل
اعتماد ہے کیونکہ ابن ہشام نے تو اسے بغیر کسی قسم کی سند کے لکھا ہے اور ابو داؤد نے جوسند دی ہے وہ کمزور
اور ناقص ہے.اس سند میں ابن اسحاق یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ زمین بن ثابت کے ایک
آزاد کردہ غلام سے سنا تھا اور اس نا معلوم الاسم غلام نے محیصہ کی ایک نامعلوم الاسم لڑکی سے سنا تھا اور
اس لڑکی نے اپنے باپ سے سنا تھا.الخ.اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کی روایت جس کے دوراوی
بالکل نامعلوم الاسم اور مجہول الحال ہوں ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکتی اور درایت کے لحاظ سے بھی غور کیا
جاوے تو یہ قصہ درست ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریق عمل اس بات کو قطعی
طور پر جھٹلاتا ہے کہ آپ نے اس قسم کا عام حکم دیا ہو.علاوہ ازیں اگر کوئی عام حکم ہوتا تو یقینا اس کے نتیجہ
میں کئی قتل واقع ہو جاتے مگر روایت میں صرف ایک قتل کا ذکر ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی عام حکم
نہیں تھا اور پھر جب صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ دوسرے دن ہی یہود کے ساتھ نیا معاہدہ ہو گیا تھا کے
تو اس صورت میں یہ ہرگز قبول نہیں کیا جاسکتا کہ اس معاہدہ کے ہوتے ہوئے اس قسم کا حکم دیا گیا ہوا اور اگر
اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا تو یہودی لوگ اس کے متعلق ضرور واویلا کرتے ، مگر کسی تاریخی روایت سے ظاہر
1 : سنن ابوداؤ د کتاب الخراج
: ابودا و دوا بن سعد
Page 553
۵۳۸
نہیں ہوتا کہ یہود کی طرف سے کبھی کوئی اس قسم کی شکایت کی گئی ہو.پس روایت اور درایت دونوں
طرح سے یہ قصہ غلط ثابت ہوتا ہے اور اگر اس میں کچھ حقیقت کبھی جاسکتی ہے تو صرف اس قدر کہ جب
کعب بن اشرف کے قتل کے بعد مدینہ میں ایک شور پیدا ہوا اور یہودی لوگ جوش میں آگئے تو اس وقت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے صحابہ سے یہ فرمایا ہوگا کہ جس
یہودی کی طرف سے تمہیں خطرہ ہو اور تم پر حملہ کرے تم اسے دفاع میں قتل کر سکتے ہو ،مگر معلوم ہوتا ہے کہ
یہ حالت صرف چند گھنٹے رہی تھی.کیونکہ دوسرے دن ہی یہود کے ساتھ از سرنو معاہدہ ہوکر امن وامان
کی صورت
پیدا ہوگئی تھی.واللہ اعلم
کعب بن اشرف کے قتل کی تاریخ کے متعلق کسی قدر اختلاف ہے.ابن سعد نے اسے ربیع الاول
۳ ہجری میں بیان کیا ہے لیکن ابن ہشام نے اسے سریہ زید بن حارثہ کے بعد رکھا ہے جو مسلم طور پر
جمادی الآخرۃ میں واقع ہوا تھا.میں نے اس جگہ ابن ہشام کی ترتیب ملحوظ رکھی ہے.حفصہ بنت عمر کی شادی شعبان ۳ ہجری حضرت عمر بن خطاب کی ایک صاحبزادی تھیں جن کا
نام حفصہ تھا.وہ خنیس بن حذافہ کے عقد میں
تھیں جو ایک مخلص صحابی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے.بدر کے بعد مدینہ واپس آنے پر تنیس
بیمار ہو گئے اور اس بیماری سے جانبر نہ ہو سکے.ان کی وفات کے کچھ عرصہ بعد حضرت عمرؓ کو حفصہ کے
نکاح ثانی کا فکر دامن گیر ہوا.اس وقت حفصہ کی عمر میں سال سے اوپر تھی." حضرت عمر نے اپنی فطرتی
سادگی میں خود عثمان بن عفان سے مل کر ان سے ذکر کیا کہ میری لڑکی حفصہ اب بیوہ ہے، آپ اگر پسند
کریں تو اس کے ساتھ شادی کر لیں ، مگر حضرت عثمان نے ٹال دیا.اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت
ابوبکر سے ذکر کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے بھی خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا..اس پر حضرت عمرؓ کو
بہت ملال ہوا اور انہوں نے اسی ملال کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر
آپ سے ساری سرگزشت عرض کر دی.آپ نے فرمایا.عمر! کچھ فکر نہ کرو.خدا کو منظور ہوا تو حفصہ کو عثمان
وابوبکر کی نسبت بہتر خاوند مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ کی نسبت بہتر بیوی ملے گی.یہ آپ نے اس لئے
فرمایا کہ آپ حفصہ کے ساتھ شادی کر لینے اور اپنی لڑکی ام کلثوم کو حضرت عثمان کے ساتھ بیاہ کر دینے
ل : اصابه وزرقانی
: اصابه وزرقانی حالات حفصہ
سے بخاری کتاب النکاح باب عرض الانسان ابنته : اصابه وزرقانی حالات حفصہ
Page 554
۵۳۹
کا ارادہ کر چکے تھے جس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان دونوں کو اطلاع تھی اور اسی لئے انہوں نے
حضرت عمر کی تجویز کو ٹال دیا تھا.اس کے کچھ عرصہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی
صاحبزادی ام کلثوم کی شادی فرما دی جس کا اوپر ذکر گزر چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے خود اپنی طرف
سے حضرت عمر کو حفصہ کے لئے پیغام بھیجا.حضرت عمرؓ کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہئے تھا.انہوں نے
نہایت خوشی سے اس رشتہ کو قبول کیا.اور شعبان ۳ ہجری میں حضرت حفصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
نکاح میں آکر حرم نبوی میں داخل ہو گئیں.جب یہ رشتہ ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ
شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی ملال ہو.بات یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ارادے سے اطلاع تھی لیکن میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا.ہاں اگر
آپ کا یہ ارادہ نہ ہوتا تو میں بڑی خوشی سے حفصہ سے شادی کر لیتا ہے
حفصہ کے نکاح میں ایک تو یہ خاص مصلحت تھی کہ وہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں جو گویا حضرت ابوبکر
کے بعد تمام صحابہ میں افضل ترین سمجھے جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین خاص میں سے
تھے.پس آپس کے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے اور حضرت عمر اور حفصہ کے اس صدمہ کی تلافی کرنے
کے واسطے جو تنیس بن حذافہ کی بے وقت موت سے ان کو پہنچا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب
سمجھا کہ حفصہ سے خود شادی فرمالیں اور دوسری عام مصلحت یہ مد نظر تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنا ہی عورتوں میں جو بنی نوع انسان کا نصف حصہ بلکہ بعض جہات سے
نصف بہتر حصہ ہیں دعوت
و تبلیغ اور تعلیم کا کام زیادہ وسیع پیمانے پر اور زیادہ آسانی اور زیادہ خوبی کے
ساتھ ہو سکے گا.تعد دازدواج کے مسئلہ کے متعلق اصولی بحث ہم حضرت عائشہ کی شادی کے بیان میں کر چکے ہیں.اس جگہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں لیکن اس قدر ذکر اس جگہ بے موقع نہ ہوگا کہ جو پابندیاں تعدد
ازدواج کے متعلق اسلام عائد کرتا ہے اور جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود عملاً کار بند تھے ان کے
ماتحت ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ شادی کرنا ہر گز عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا بلکہ حق یہ ہے کہ
ان شرائط کے ماتحت تعدّ دازدواج ایک بہت بڑی قربانی ہے جو مرد اور عورت دونوں کو اپنے ذاتی یا
خاندانی یا قومی یا ملکی یا دینی مصالح کے ماتحت اختیار کرنی پڑتی ہے اور اس قربانی کو اختیار کرنے والا شخص
ل بخاری کتاب النکاح
: طبری حالات ۳ ھ سے بخاری کتاب النکاح
Page 555
۵۴۰
خانگی عیش و عشرت اور خانگی راحت و خوشی سے اس شخص کی نسبت بہت زیادہ دور ہوتا ہے جس کے مال
اور جس کی توجہ اور جس کے وقت اور جس کی ظاہری محبت کی مالک صرف ایک عورت ہوتی ہے.پھر یہ بات
بھی یاد رکھنی چاہئے کہ جو شخص عیش و عشرت کے خیال سے زیادہ شادیاں کرتا ہے، وہ لازماً اپنی بیویوں کی
خوراک اور پوشش اور رہائش وغیرہ کا خاص خیال رکھتا ہے اور ان کے لئے ہر طرح کا سامان عیش وعشرت
مہیا کرتا ہے.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل اس کے خلاف نظارہ نظر آتا ہے.دور نہ
جاؤ قرآن ہی کو کھول کر دیکھو کہ جو مسلم طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح میں صحیح ترین صحیفہ ہے کہ
ایک موقع پر جبکہ باہر سے اموال کی آمد آمد شروع ہو گئی تھی اور صحابہ کسی قدر خوشحال ہورہے تھے آپ کی
بیویوں نے آپ سے عرض کیا کہ اب اس فراخی سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چاہئے اور اب تک جو تنگی کے دن
کاٹے ہیں اس کا کچھ ازالہ ہونا چاہئے تو اس پر آپ نے فرمایا.إن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيُوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِحْكُنَّ
سَرَاحًا جَمِيْلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
اَعَدَّ لِلْمُحْسِلتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًاO
یعنی اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کے مال و متاع کو پسند کرتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کے
اموال دے دیتا ہوں ،مگر اس صورت میں تم میری بیویاں نہیں رہ سکتیں ( کیونکہ میں اپنی
زندگی کو دنیا کے اموال کی آلائش سے پاک رکھنا چاہتا ہوں ) اور اگر میری بیویاں رہنا
چاہتی ہو تو محض خدا کی خاطر اور میرے منصب رسالت کی خاطر اور آخرت کی خاطر میرے
ساتھ رہو.اس صورت میں تم کو خدا کی طرف سے وہ عظیم الشان اجر ملے گا جو نیکو کاروں
کے لئے مقدر ہے.“
آپ کے اس فرمان کو سن کر سب ازواج نے بالا تفاق عرض کیا کہ ہمیں خدا اور اس کا رسول بس
ہیں.دنیا کے اموال در کار نہیں.ج کیا اس زبر دست تاریخی شہادت کے ہوتے ہوئے یہ خیال کیا جاسکتا
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدد ازدواج نعوذ باللہ عیش وعشرت کا ذریعہ تھا ؟ یقینا یقیناً ہرنئی
بیوی جو آپ کے گھر آتی تھی وہ آپ کی خانگی تنگی کو زیادہ کرنے والی ہوتی تھی اور یہ آپ کی عظیم الشان
قربانی کی روح تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے دین اور اپنی قوم اور اپنے ملک کی خاطر ان
بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ احزاب
سورة احزاب : ۳۰،۲۹
Page 556
۵۴۱
تنگیوں کو خوشی کے ساتھ برداشت کیا اور اپنی زندگی کے امن اور قرار کو بربادکر کے ایک بالکل درویشانہ اور
مسافرانہ زندگی اختیار کی.آپ کے پیش کردہ مسئلہ تعد دازدواج میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس سے وہ علائق کمزور ہو
جائیں جو دنیا میں انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں.ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کے بہت سے تعلقات ہیں
جن کو اسے نبھانا پڑتا ہے.مثلاً والدین ہیں ، بھائی بہن ہیں ، بیوی ہے، اولاد ہے، دوست ہیں، ہمسائے
ہیں وغیر ذالک.اور ان سارے علائق میں سے جذباتی رنگ میں سب سے زیادہ گرم جوشی اور حدت حس کا
رشتہ بیوی کا رشتہ ہے.مرد کی محبت اپنی بیوی سے بعض اوقات ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے جسے عرف عام
میں عشق کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور بعض اوقات جذبات کی تیزی اس عشق کو ایک گونہ جنون کی
حد تک بھی پہنچا دیتی ہے اور پھر ایسی حالت میں انسان سوائے اس عشق کے مظاہرے میں زندگی گزارنے
کے اور کسی کام کا نہیں رہتا.حالانکہ یہ مسلم ہے کہ دنیا کی زندگی کے بہترین کام وہ ہیں جو انفرادی زندگی
کے ساتھ نہیں بلکہ اجتماعی اور قومی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں.پس چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
انسان کے اندران فرائض کے پورا کرنے کے لئے بہترین قابلیت پیدا کرنا چاہتے تھے جو بنی نوع انسان
کی اجتماعی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لئے آپ نے بعض حالات میں خاص شرائط کے ماتحت
تعد دازدواج کی اجازت دے کر مرد اور عورت کے اس رشتے کو ایسی صورت دے دی ہے کہ اس کے اندر
محویت کا عالم نہ پیدا ہو سکے.اور اس اصل کے ماتحت آپ کا تعدد ازدواج پر عمل کرنا علائق خانگی کو کمزور
کرنے کی غرض سے تھا نہ کہ انہیں مضبوط کرنے کے واسطے.چنانچہ آپ کا وہ جواب جو آپ نے اپنی
بیویوں کو ان کی طرف سے مال کا مطالبہ ہونے پر دیا اس پر شاہد ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نہ صرف
خود اپنی توجہ کو خدا کے لئے اور اپنے منصب رسالت کے لئے وقف رکھنا چاہتے تھے بلکہ اپنی بیویوں کے
متعلق بھی آپ کے دل میں یہی خواہش تھی کہ ان کا آپ کے ساتھ تعلق محض خدا کے لئے اور آپ کے
منصب رسالت کے لئے اور آخرت کے لئے ہو.الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعد دازدواج دینی
اور قومی اور ملکی مفاد کے ماتحت تھا اور ان حالات میں یقیناً یہ ایک شخصی مفاد کی بہت بڑی قربانی تھی جو آپ
نے اختیار کی کیونکہ آپ نے اپنی خانگی زندگی میں ایک سخت درجہ تلخی اور تنگی پیدا کر کے اپنے ان فرائض کے
انجام دینے کے لئے آسانی پیدا کی جو ایک شارع اور دینی مصلح اور لیڈر کی حیثیت میں آپ پر عائد ہوتے
تھے اور اس لئے آپ کا یہ فعل ہر اس شخص کے شکریہ کا مستحق ہے جو جنگل کے وحشی جانوروں کی طرح صرف
Page 557
۵۴۲
اپنی جسمانی خواہشات اور شخصی اور انفرادی مفاد کا خیال نہیں رکھتا بلکہ اخلاقی اور روحانی اور قومی اور اجتماعی
زندگی کی اصلاح اور ترقی کو اپنا نصب العین بناتا ہے.حضرت حفصہ کی عمر شادی کے وقت قریباً اکیس سال تھی اور بوجہ اس کے کہ حضرت عائشہ کے بعد وہ
صحابہ میں سے ایک افضل ترین شخص کی صاحبزادی تھیں.ازواج مطہرات میں ان کا ایک خاص درجہ سمجھا
جاتا ہے اور حضرت عائشہ کے ساتھ بھی ان کا بہت جوڑ تھا اور سوائے کبھی کبھار کی کش مکش کے جو ایسے رشتہ
میں ہو جایا کرتی ہے، وہ دونوں آپس میں بہت محبت کے ساتھ رہتی تھیں.حضرت حفصہ لکھنا پڑھنا جانتی
تھیں.چنانچہ حدیث میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک صحابی عورت شفاء بنت عبداللہ سے لکھنا
سیکھا تھا.ان کی وفات ۴۵ ہجری میں ہوئی جبکہ ان کی عمر کم و بیش تریسٹھ سال کی تھی.ولادت امام حسن رمضان ۳ ہجری ۲ ہجری کے واقعات میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے
نکاح کا ذکر گزر چکا ہے.ان کے ہاں رمضان ۳ ہجری میں
یعنی نکاح کے قریباً دس ماہ بعد ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رکھا.یہ وہی
حسن ہیں جو بعد میں مسلمانوں میں امام حسن علیہ الرحمہ کے نام سے ملقب ہوئے.حسنؓ اپنی شکل وصورت
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنی اولاد
حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی اسی طرح حضرت فاطمہ کی اولاد سے بھی آپ کو خاص محبت تھی.کئی دفعہ
فرماتے تھے خدایا مجھے ان بچوں سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے
محبت کر کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ نماز میں ہوتے تو حسنؓ آپ سے لپٹ جاتے.رکوع میں ہوتے تو
آپ کی ٹانگوں میں سے راستہ بنا کر نکل جاتے.بعض اوقات جب صحابہ انہیں روکتے تو آپ صحابہ کو منع
فرما دیتے کہ روکو نہیں.دراصل چونکہ ان کا لپٹنا آپ کی توجہ کو منتشر نہیں کرتا تھا.اس لئے آپ ان کی
معصوم محبت کے طفلانہ مظاہرہ میں مزاحم نہیں ہونا چاہتے تھے.امام حسنؓ کے متعلق ایک دفعہ آپ نے فرمایا
کہ میرا یہ بچہ سید یعنی سردار ہے اور ایک وقت آئے گا کہ خدا اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دوگر ہوں
میں صلح کرائے گا.چنانچہ اپنے وقت پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی.تے
ل ابوداؤد کتاب الطب باب ماجاء في الرقى
استیعاب واصا به واسدالغابه و بخاری
Page 558
۵۴۳
ایک مصیبت کا دھکہ.قانون ورثہ.حرمت شراب
کفار کی غداری اور دو دردناک واقعات
جنگ اُحد شوال ۳ ہجری مطابق مارچ ۶۲۴ ء جنگ بدر کے نتیجے میں جو ماتم عظیم مکہ میں
بر پا ہوا تھا اس کا ذکر جنگ بدر کے حالات
میں کیا جا چکا ہے.سرداران قریش نے قسمیں کھائی تھیں کہ جب تک مقتولین بدر کا انتقام نہ لے لیں
گے اس وقت تک چین نہ لیں گے.ان کے اس جذبہ انتقام کو مدینہ کے بدعہد یہود کی خفیہ اشتعال
انگیزیوں نے اور بھی زیادہ بھڑ کا دیا تھا.چنانچہ بدر کے بعد قریش مکہ نے دوسرے قبائل کو مسلمانوں
کے خلاف بہت سخت اکسانا شروع کر دیا اور خود بھی برابر اس تاک میں رہے کہ جب بھی موقع ملے
مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں کچل ڈالیں.بنو سلیم اور بنو غطفان کا مدینہ پر حملہ آور ہونے کی غرض سے
بار بار جمع ہونا جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے زیادہ تر قریش مکہ ہی کی اشتعال انگیزیوں کا نتیجہ تھا.غزوہ
سویق بھی جس میں ابوسفیان نے مدینہ پر شب خون مارنے کی تجویز کی تھی اسی زنجیر کی ایک کڑی تھی
اور چونکہ خدا کے فضل سے اس غزوہ میں قریش کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اس لئے ان کا جوش انتقام
اور بھی زیادہ ہو گیا تھا اور گو اس وقت انہوں نے عرب کے سامنے اپنی عزت رکھنے کے لئے یہ کہہ دیا
تھا کہ ہماری قسم پوری ہو گئی ہے، لیکن ان کے دل اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ غزوہ سویق نے ان
کے ماتھے پر ذلت کا ایک اور دھبہ لگا دیا تھا.لہذا اس کے بعد انہوں نے آگے سے بھی زیادہ جوش
وخروش کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کی.چنانچہ غزوہ اُحد جس کا ہم اب ذکر کر نے لگے ہیں اسی
تیاری کا نتیجہ تھا.جس تجارتی قافلہ کا ذکر جنگ بدر کے حالات میں گزر چکا ہے اس کے منافع کا روپیہ جس کی مالیت
Page 559
۵۴۴
پچاس ہزار دینا تھی.رؤسائے مکہ کے فیصلہ کے مطابق ابھی تک دارالندوہ میں مسلمانوں کے خلاف حملہ
کرنے کی تیاری کے واسطے محفوظ پڑا تھا.اب اس روپے کو نکالا گیا اور بڑے زور شور سے جنگ کی تیاری
شروع ہوئی.مسلمانوں کو اس تیاری کا علم بھی نہ ہوتا اور لشکر کفار مسلمانوں کے دروازوں پر پہنچ جاتا مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی نے تمام ضروری احتیاطیں اختیار کر رکھی تھیں.یعنی آپ نے
اپنے چچا عباس بن عبدالمطلب کو جو دل میں آپ کے ساتھ تھے مکہ میں ٹھہرے رہنے کی تاکید کر رکھی تھی
اور وہ قریش کی حرکات وسکنات سے آپ کو اطلاع دیتے رہتے تھے.چنانچہ عباس بن عبدالمطلب نے
اس موقع پر بھی قبیلہ بنو غفار کے ایک تیز روسوار کو بڑے انعام کا وعدہ دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا اور
ایک خط کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس ارادے سے اطلاع دی.اور اس قاصد
کو سخت تاکید کی کہ تین دن کے اندر اندر آپ کو یہ خط پہنچا دے.جب یہ قاصد مدینہ پہنچا تو اتفاق سے اس
وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حوالی قبا میں تشریف لے گئے ہوئے تھے.چنانچہ یہ قاصد آپ
کے پیچھے وہیں قبا میں پہنچا اور آپ کے سامنے یہ بند خط پیش کر دیا.آپ نے فوراً اپنے کاتب خاص ابی بن
کعب انصاری کو یہ خط دیا اور فرمایا کہ اسے پڑھ کر سناؤ کہ کیا لکھا ہے ابی نے خط پڑھ کر سنایا تو اس میں یہ
وحشت ناک خبر درج تھی کہ قریش کا ایک جرار لشکر مکہ سے آرہا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط سن
کرابی بن کعب کو تاکید فرمائی کہ اس کے مضمون سے کسی کو اطلاع نہ ہو.اور پھر آپ نے مدینہ میں واپس
تشریف لا کر اپنے دوصحابیوں کو شکر قریش کی خبر رسانی کے لئے مکہ کے راستہ کی طرف روانہ
فرما دیا.غالباً اسی موقع پر آپ نے مسلمانوں کی تعداد و طاقت معلوم کرنے کے لئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ
مدینہ کی تمام مسلمان آبادی کی مردم شماری کی جاوے.چنانچہ مردم شماری کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس وقت تک
کل پندرہ سو مسلمان متنفس ہیں.اس وقت کے حالات کے ماتحت اسی تعداد کو بہت بڑی تعداد
سمجھا گیا.چنانچہ بعض صحابہ نے تو اس وقت خوشی کے جوش میں یہاں تک کہہ دیا کہ کیا اب بھی جبکہ ہماری تعداد
ڈیڑھ ہزار تک پہنچ گئی ہے ہمیں کسی کا ڈر ہو سکتا ہے؟ مگر انہی میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد
ہم پر ایسے ایسے سخت وقت آئے کہ بعض اوقات ہمیں نماز بھی چھپ چھپ کر ادا کرنی پڑتی تھی.ایک
ابن سعد
زرقانی جلد اصفحه ۴۴۸
: ابن سعد : ابن سعد وابن ہشام
ه: ابن سعد
بخاری کتاب الجہاد باب کتابتہ الامام و فتح الباری شرح حدیث مذکور
زرقانی جلد ۲ صفحه ۲۱
Page 560
۵۴۵
موقع پر اس سے پہلے بھی آپ نے مسلمانوں کی مردم شماری کروائی تھی تو اس وقت چھ اور سات سو کے
در میان تعدا د نکلی تھی.غالبًا رمضان ۳ ہجری کے آخر یا شوال کے شروع میں قریش کا لشکر مکہ سے نکالا.لشکر میں دوسرے قبائل
عرب کے بہت سے بہادر بھی شامل تھے.ابوسفیان سردار شکر تھا.لشکر کی تعداد تین ہزار تھی جس میں سات سو
زرہ پوش سپاہی شامل تھے.سواری کا سامان بھی کافی تھا یعنی دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے.اور
سامان حرب بھی کافی وشافی مقدار میں تھا.عورتیں بھی ساتھ تھیں جن میں ہند زوجہ ابوسفیان اور عکرمہ بن
ابو جہل ، صفوان بن امیہ، خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کی بیویاں اور مصعب بن عمیر صحابی کی مشرکہ ماں
خاص طور پر قابل ذکر ہیں یا یہ عورتیں عرب کی قدیم رسم کے مطابق گانے بجانے کا سامان اپنے ساتھ لائی
تھیں تا کہ اشتعال انگیز اشعار گا کر اور دفیں بجا کر اپنے مردوں کو جوش دلاتی رہیں.قریش کا یہ لشکر دس گیارہ دن کے سفر کے بعد مدینہ کے پاس پہنچا اور چکر کاٹ کر مدینہ کے شمال کی
طرف احد کی پہاڑی کے پاس ٹھہر گیا.اس جگہ کے قریب ہی عریض کا سرسبز میدان تھا جہاں مدینہ کے
مویشی چرا کرتے تھے اور کچھ کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی.قریش نے سب سے پہلے اس چراگاہ پر حملہ کر کے
اس میں من مانی غارت مچائی.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مخبروں سے لشکر قریش کے قریب
آجانے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی حباب بن منذر کو روانہ فرمایا کہ وہ جا کر دشمن
کی تعداد اور طاقت کا پتہ لائیں.اور آپ نے انہیں تاکید فرمائی کہ اگر دشمن کی طاقت زیادہ ہو اور
مسلمانوں کے لئے خطرہ کی صورت ہو تو واپس آکر مجلس میں اس کا ذکر نہ کریں بلکہ علیحدگی میں اطلاع دیں
تا کہ اس سے کسی قسم کی بددلی نہ پھیلے.احباب خفیہ خفیہ گئے اور نہایت ہوشیاری سے تھوڑی دیر میں ہی واپس
آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے حالات عرض کر دئے.یہ جمعرات کا دن تھا اور اب لشکر
قریش کی آمد کی خبر مدینہ میں پھیل چکی تھی اور عریض پر جو ان کا حملہ ہوا تھا اس کی اطلاع بھی عام ہو چکی تھی
اور گو عامۃ الناس کو لشکر کفار کے تفصیلی حالات کا علم نہیں دیا گیا تھا مگر پھر بھی یہ رات مدینہ میں سخت خوف
اور خطرہ کی حالت میں گزری.خاص خاص صحابہ نے ساری رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے
مسلم کتاب الایمان باب جواز الاستسمراء للخائف
ابن ہشام
: ابن سعد
: ابن سعد وابن ہشام
ه: ابن سعد
: ابن سعد
ك واقدی
Page 561
۵۴۶
اردگرد پہرہ دیا یے صبح جمعہ کا دن تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے قریش
کے اس حملہ کے متعلق مشورہ مانگا کہ آیا مدینہ میں ہی ٹھہرا جاوے یا باہر نکل کر مقابلہ کیا جاوے.اس مشورہ
میں عبد اللہ بن ابی بن سلول بھی شریک تھا جو دراصل تو منافق تھا مگر بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہو چکا تھا
اور یہ پہلا موقع تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشورہ میں شرکت کی دعوت دی.مشورہ سے قبل
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے حملے اور ان کے خونی ارادوں
کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ” آج رات
میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی ہے اور نیز میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا سراٹوٹ گیا ہے.اور پھر
میں نے دیکھا کہ وہ گائے ذبح کی جارہی ہے اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط اور محفوظ
زرہ کے اندر ڈالا ہے.اور ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”میں نے دیکھا ہے
کہ ایک مینڈھا ہے جس کی پیٹھ پر میں سوار ہوں.صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ ! آپ نے اس
خواب کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا.گائے کے ذبح ہونے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے
صحابہ میں سے بعض کا شہید ہونا مراد ہے اور میری تلوار کے کنارے کے ٹوٹنے سے میرے عزیزوں میں
سے کسی کی شہادت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے.یا شاید خود مجھے اس مہم میں کوئی تکلیف پہنچے.اور زرہ
مناسب ہے.کے اندر ہاتھ ڈالنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حملہ کے مقابلہ کے لئے ہمارا مدینہ کے اندر ٹھہر نا زیادہ
ہے.اور مینڈھے پر سوار ہونے والے خواب کی آپ نے یہ تاویل فرمائی کہ اس سے کفار کے
لشکر کا سردار یعنی علمبر دار مراد ہے جو انشاء اللہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا.اس کے بعد آپ نے
صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا کہ موجودہ صورت میں کیا کرنا چاہئے.بعض اکابر صحابہ نے حالات کے اور پیچ پیچ
کو سوچ کر اور شاید کسی قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سے بھی متاثر ہوکر یہ رائے دی کہ مدینہ
میں ہی ٹھہر کر مقابلہ کرنا مناسب ہے یہی رائے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے دی
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پسند فرمایا اور کہا کہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مدینہ کے
اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں لیکن اکثر صحابہ نے خصوصاً ان نو جوانوں نے جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں
ہوئے تھے اور اپنی شہادت سے خدمت دین کا موقع حاصل کرنے کے لئے بے تاب ہورہے تھے بڑے
بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب باب و ا مرهم شوری
ابن سعد
بخاری حالات احد
ابن ہشام
ه : ابن سعد
ابن ہشام
ک: ابن سعد
ابن سعد
2 : زرقانی وابن سعد
Page 562
۵۴۷
اصرار کے ساتھ عرض کیا کہ شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہئے.ان لوگوں نے اس قدر
اصرار کے ساتھ اپنی رائے کو پیش کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھ کر ان کی بات
مان لی اور فیصلہ فرمایا کہ ہم کھلے میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد
آپ نے مسلمانوں میں عام تحریک فرمائی کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے اس غزوہ میں شامل ہوکر
ثواب حاصل کریں.اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی
مدد سے آپ نے عمامہ باندھا اور لباس پہنا اور پھر ہتھیار لگا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے باہر تشریف لے
آئے.لیکن اتنے عرصہ میں حضرت سعد بن معاذ رئیس قبیلہ اوس اور دوسرے اکابر صحابہ کے سمجھانے سے
نوجوان پارٹی کو اپنی غلطی محسوس ہونے لگی تھی کہ رسول خدا کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے پر اصرار
نہیں کرنا چاہئے تھا اور اب اکثر ان میں سے پشیمانی کی طرف مائل تھے.جب ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار لگائے اور دوہری زرہ اور خود وغیرہ پہنے ہوئے
تشریف لاتے دیکھا تو ان کی ندامت اور بھی زیادہ ہوگئی اور انہوں نے قریباً یک زبان ہو کر عرض کیا کہ
یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے پر اصرار کیا.آپ مجس
طرح مناسب خیال فرماتے ہیں اسی طرح کا رروائی فرما ئیں.انشاء اللہ اسی میں برکت ہوگی.آپ نے
فرمایا.”خدا کے نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر اسے اتار دے قبل اس کے کہ خدا کوئی
فیصلہ کرے.پس اب اللہ کا نام لے کر چلو اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت
تمہارے ساتھ ہوگی.اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلامی کے لئے تین جھنڈے تیار
کروائے.قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن الحضیر کے سپرد کیا گیا اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر کے
ہاتھ میں دیا گیا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا اور پھر مدینہ میں عبداللہ بن ام مکتوم کو امام الصلوۃ
مقرر کر کے آپ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے ہمراہ نماز عصر کے بعد مدینہ سے نکلے.قبیلہ اوس اور خزرج
کے رؤساء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ آپ کی سواری کے سامنے آہستہ آہستہ دوڑتے جاتے تھے اور
باقی صحابہ آپ کے دائیں اور بائیں اور پیچھے چل رہے تھے.اُحد کا پہاڑ مدینہ کے شمال کی طرف قریبا تین
میل کے فاصلہ پر واقع ہے.اس کے نصف میں پہنچ کر اس مقام میں جسے شیخین کہتے ہیں آپ نے قیام
ابن ہشام وابن سعد
: ابن سعد وزرقانی
بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب باب امرهم شوری
ابن سعد ه : ابن سعد وطبری
Page 563
۵۴۸
فرمایا اور لشکر اسلامی کا جائزہ لئے جانے کا حکم دیا.کم عمر بچے جو جہاد کے شوق میں ساتھ آگئے تھے واپس
کئے گئے.چنانچہ عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، ابوسعید خدری وغیرہ سب واپس کئے گئے.رافع بن خدیج
انہیں بچوں کے ہم عمر تھے مگر تیراندازی میں اچھی مہارت رکھتے تھے.ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کے
والد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی سفارش کی کہ ان کو شریک جہاد ہونے کی اجازت
دی جاوے.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سپاہیوں کی طرح خوب تن کر
کھڑے ہو گئے تا کہ چست اور لمبے نظر آئیں.چنانچہ ان کا یہ داؤ چل گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرما دی.اس پر ایک اور بچہ سمرۃ بن جندب نامی جسے واپسی کا حکم مل
چکا تھا اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر رافع کو لیا گیا ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہئے.کیونکہ میں رافع
سے مضبوط ہوں اور اسے کشتی میں گرا لیتا ہوں.باپ کو بیٹے کے اس اخلاص پر بہت خوشی ہوئی اور وہ اسے
ساتھ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی خواہش بیان کی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا رافع اور سمرۃ کی کشتی کرواؤ تا کہ معلوم ہو کہ کون
زیادہ مضبوط ہے.چنانچہ مقابلہ ہوا اور واقع میں سمرۃ نے پل بھر میں رافع کو اٹھا کر دے مارا.جس پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرۃ کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس معصوم بچے کا دل خوش
ہو گیا.اب چونکہ شام ہو چکی تھی اس لئے بلال نے اذان کہی اور سب صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی اقتدا میں نماز ادا کی اور پھر رات کے واسطے مسلمانوں نے یہیں ڈیرے ڈال دئے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے رات کے پہرے کے لئے محمد بن مسلمہ کو منتظم مقر فرمایا جنہوں نے پچاس صحابہ کی جماعت
کے ساتھ رات بھر لشکر اسلامی کے اردگرد چکر لگاتے ہوئے پہرہ دیا.کے
دوسرے دن یعنی ۱۵ شوال ۳ ہجری مطابق ۳۱ مارچ ۶۲۴ء بروز ہفتہ سحری کے وقت لشکر اسلامی
آگے بڑھا اور راستے میں نماز ادا کرتے ہوئے صبح ہوتے ہی اُحد کے دامن میں پہنچ گیا.اس موقع
پر بد باطن عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے غداری کی اور اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ
مسلمانوں کے لشکر سے ہٹ کر یہ کہتا ہوا مدینہ کی طرف واپس لوٹ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری
بات نہیں مانی اور نا تجربہ کارنوجوانوں کے کہنے میں آ کر باہر نکل آئے ہیں، اس لئے میں ان کے ساتھ
ا: ابن سعد
: ابن ہشام وطبری
: ابن سعد
ابن ہشام
۵: توفیقات
Page 564
۵۴۹
ہو کر نہیں لڑسکتا.بعض لوگوں نے بطور خود اسے سمجھایا بھی کہ یہ غداری ٹھیک نہیں ہے، مگر اس نے ایک نہ
سنی اور یہی کہتا گیا کہ یہ کوئی لڑائی ہوتی تو میں بھی شامل ہوتا مگر یہ کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ خود ہلاکت کے
منہ میں جانا ہے یا اب اسلامی لشکر کی تعداد صرف سات سو نفوس پر مشتمل تھی جو کفار کے تین ہزار سپاہیوں
کے مقابلہ میں ایک چہارم سے بھی کم تھی اور سواری اور سامان حرب کے لحاظ سے بھی اسلامی لشکر قریش
کے مقابلہ میں بالکل کمزور اور حقیر تھا.کیونکہ مسلمانوں کی فوج میں صرف ایک سو زرہ پوش اور فقط دو
گھوڑے تھے..اس کے بالمقابل کفار کے لشکر میں سات سو زرہ پوش اور دوسو گھوڑے اور تین ہزار
اونٹ تھے.اس کمزوری کی حالت میں جسے مسلمان خوب محسوس کرتے تھے عبداللہ بن ابی کے تین سو
آدمی کی غداری نے بعض کمزور دل مسلمانوں میں ایک بے چینی اور اضطراب کی حالت پیدا کر دی اور
ان میں سے بعض متزلزل ہونے لگ گئے.چنانچہ جیسا کہ قرآن شریف سے میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اسی
گھبراہٹ اور اضطراب کی حالت میں مسلمانوں کے دو قبائل بنو حارثہ اور بنوسلمہ نے مدینہ کی طرف
واپس لوٹ جانے کا ارادہ بھی کر لیا، مگر چونکہ دل میں نور ایمان موجود تھا پھر سنبھل گئے اور ظاہری
اسباب کے لحاظ سے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے آقا کے پہلو کو نہ چھوڑا." آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اُحد کے دامن میں ڈیرہ ڈال دیا.ایسے
طریق پر کہ اُحد کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے کی طرف آگئی اور مدینہ گویا سامنے رہا.اور اس طرح
آپ نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا.عقب کی پہاڑی میں ایک درہ تھا جہاں سے حملہ ہوسکتا تھا.اس کی
حفاظت کا آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں پچاس تیرانداز صحابی وہاں متعین
فرما دئے اور ان کو تاکید فرمائی کہ خواہ کچھ ہو جاوے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور دشمن پر تیر برساتے
جائیں.آپ کو اس درہ کی حفاظت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے عبداللہ بن جبیر سے بہ تکرار فرمایا کہ
دیکھو یہ درہ کسی صورت میں خالی نہ رہے.حتی کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہوگئی ہے اور دشمن پسپا ہو کر
ہوکر
بھاگ نکلا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا اور اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوگئی ہے اور دشمن ہم پر
غالب آ گیا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ سے نہ ہٹنا ہے حتی کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم
دیکھو کہ پرندے ہما را گوشت نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا حتی کہ تمہیں یہاں سے
ابن ہشام وابن سعد
طبری
: سورة آل عمران : ۱۲۳
بخاری حالات غزوہ احد
بخاری کتاب المغازی حالات احد
Page 565
۵۵۰
آنے کا حکم جاوے.اس طرح اپنے عقب کو پوری طرح محفوظ کر کے آپ نے لشکر اسلامی کی صف
بندی کی اور مختلف دستوں کے جدا جدا امیر مقرر فرمائے.اس موقع پر آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ
لشکر قریش کا جھنڈ ا طلحہ کے ہاتھ میں ہے.طلحہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے مورث اعلیٰ
قصی بن کلاب کے قائم کردہ انتظام کے ماتحت جنگوں میں قریش کی علمبر داری کا حق رکھتا تھا.یہ معلوم
کر کے آپ نے فرمایا.ہم قومی وفاداری دکھانے کے زیادہ حق دار ہیں چنانچہ آپ نے حضرت علی
سے مہاجرین کا جھنڈا لے کر مصعب بن عمیر کے سپرد فرما دیا جو اسی خاندان کے ایک فرد تھے جس سے
طلحہ تعلق رکھتا تھا ہے
دوسری طرف قریش کے لشکر میں بھی صف آرائی ہو چکی تھی.ابو سفیان امیر العسکر تھا.میمنہ پر
خالد بن ولید کمانڈر تھا.رتھا.اور میسرہ پر عکرمہ بن ابو جہل تھا.تیر انداز عبداللہ بن ربیعہ کی کمان میں تھے.کے
عورتیں لشکر کے پیچھے دفیں بجا بجا کر اور اشعار گا گا کر مردوں کو جوش دلاتی تھیں ہے
سب سے پہلے لشکر قریش سے ابو عامر اور اس کے ساتھی آگے بڑھے.اس شخص کا ذکر اوپر گزر چکا ہے
کہ یہ قبیلہ اوس میں سے تھا اور مدینہ کا رہنے والا تھا اور راہب کے نام سے مشہور تھا.جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس کے کچھ عرصہ بعد یہ شخص بغض وحسد سے بھر گیا اور اپنے چند
ساتھیوں کے ساتھ مکہ چلا گیا اور قریش مکہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہا.چنانچہ اب جنگ احد میں وہ قریش کا حمایتی بن کر مسلمانوں کے خلاف شریک جنگ ہوا اور یہ ایک عجیب
بات ہے کہ ابو عامر کا بیٹا نظلہ ایک نہایت مخلص مسلمان تھا اور اس جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر میں شامل
تھا اور نہایت جانبازی کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا.ابو عامر چونکہ قبیلہ اوس کے ذی اثر لوگوں میں سے تھا.اس لئے اسے یہ پختہ امید تھی کہ اب جو میں اتنے عرصہ کی جدائی کے بعد مدینہ والوں کے سامنے ہوں گا تو
وہ میری محبت میں فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے ساتھ آملیں گے.اسی امید میں ابو عامر
اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر سب سے پہلے آگے بڑھا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا.”اے قبیلہ اوس
کے لوگو ! میں ابو عامر ہوں.انصار نے یک زبان ہو کر کہا.” دور ہو جا اے فاسق ! تیری آنکھ ٹھنڈی
نہ ہو.اور ساتھ ہی پتھروں کی ایک ایسی باڑ ماری کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی بدحواس ہو کر پیچھے
،،
بخاری کتاب الجہاد باب ما يكره من التنازع
: ابن ہشام وابن سعد
۲، ۳: ابن سعد
۵: ابن ہشام
Page 566
۵۵۱
کی طرف بھاگ گئے.اس نظارہ کو دیکھ کر قریش کا علمبر دار طلحہ بڑے جوش کی حالت میں آگے بڑھا
اور بڑے متکبرانہ لہجہ میں مبارز طلبی کی.حضرت علی آگے بڑھے اور دو چار ہاتھ میں طلحہ کو کاٹ کر رکھ دیا.اس
کے بعد طلحہ کا بھائی عثمان آگے آیا اور ادھر سے اس کے مقابل پر حضرت حمزہ نکلے اور جاتے ہی اسے
مار گرایا.کفار نے یہ نظارہ دیکھا تو غضب میں آکر عام دھاوا کر دیا.مسلمان بھی تکبیر کے نعرے لگاتے
ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں غالباً اسی موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا.”کون ہے جو اسے لے کر اس کا حق ادا کرے.بہت سے صحابہ نے
اس فخر کی خواہش میں اپنے ہاتھ پھیلائے کیے جن میں حضرت عمر اور زبیر بلکہ بعض روایات کی رو سے
حضرت ابوبکر وحضرت علی بھی شامل تھے..مگر آپ نے اپنا ہاتھ روکے رکھا اور یہی فرماتے گئے.”کوئی
ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ آخر ابو دجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا.یا رسول اللہ!
مجھے عنایت فرمائیے.آپ نے یہ تلوار انہیں دے دی اور ابو دجانہ اسے ہاتھ میں لے کر تبختر کی چال
سے اکڑتے ہوئے کفار کی طرف آگے بڑھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خدا کو یہ چال
بہت نا پسند ہے ،مگر ایسے موقع پر نا پسند نہیں.زبیر جو غالباً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لینے کے سب
سے زیادہ خواہش مند تھے اور قرب رشتہ کی وجہ سے اپنا حق بھی زیادہ سمجھتے تھے دل ہی دل میں پیچ و تاب
کھانے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تلوار نہیں دی اور ابودجانہ کو دے دی
اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لئے انہوں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس میدان میں ابودجانہ کے
ساتھ ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اس تلوار کے ساتھ کیا کرتا ہے.چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ابودجانہ نے
اپنے سر پر ایک سرخ کپڑا باندھا اور اس تلوار کو لے کر حمد کے گیت گنگنا تا ہوا مشرکین کی صفوں میں گھس گیا
اور میں نے دیکھا کہ وہ جدھر جاتا تھا گویا موت بکھیرتا جاتا تھا اور میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس
کے سامنے آیا ہو اور پھر وہ بچا ہوحتی کہ وہ لشکر قریش میں سے اپنا راستہ کا تنا ہوالشکر کے دوسرے کنارے
نکل گیا جہاں قریش کی عورتیں کھڑی تھیں.ہند زوجہ ابوسفیان جو بڑے زور شور سے اپنے مردوں کو جوش
دلا رہی تھی اس کے سامنے آئی اور ابودجانہ نے اپنی تلوار اس کے اوپر اٹھائی.جس پر ہند نے بڑے زور سے
چیخ ماری اور اپنے مردوں کو امداد کے لئے بلایا.مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ آیا لیکن میں نے دیکھا کہ
مسلم باب فضائل ابودجانه وابن ہشام
ا : ابن سعد
: زرقانی
: ابن ہشام
Page 567
۵۵۲
ابودجانہ نے خود بخود ہی اپنی تلوار نیچی کر لی اور وہاں سے ہٹ آیا.زبیر روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر
میں نے ابودجانہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے تم نے تلوار اٹھائی اور پھر نیچی کر لی.اس نے کہا میرا
دل اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر چلاؤں اور عورت بھی وہ
جس کے ساتھ اس وقت کوئی مرد محافظ نہیں.زبیر کہتے ہیں.میں نے اس وقت سمجھا کہ واقعی جو حق
رسول
اللہ کی تلوار کا ابودجانہ نے ادا کیا ہے وہ شاید میں نہ کر سکتا اور میرے دل کی خلش دور ہوگئی.الغرض قریش کے علمبر دار کے مارے جانے کے بعد دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہوگئیں اور سخت
گھمسان کا رن پڑا اور ایک عرصہ تک دونوں طرف سے قتل وخون کا سلسلہ جاری رہا.آخر آہستہ آہستہ
اسلامی لشکر کے سامنے قریش کی فوج کے پاؤں اکھڑنے شروع ہوئے.چنانچہ مشہور انگریز مؤرخ
سرولیم میور لکھتے ہیں :
مسلمانوں کے خطرناک حملوں کے سامنے مکی لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگ گئے.قریش
کے رسالے نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ اسلامی فوج کے بائیں طرف عقب سے ہو کر حملہ
کریں.مگر ہر دفعہ ان کو ان پچاس تیراندازوں کے تیر کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا جومحد ( صلی اللہ علیہ وسلم)
نے وہاں خاص طور پر متعین کئے ہوئے تھے.مسلمانوں کی طرف سے اُحد کے میدان میں بھی
وہی شجاعت و مردانگی اور موت و خطر سے وہی بے پروائی دکھائی گئی جو بدر کے موقع پر انہوں نے
دکھائی تھی.مکہ کے لشکر کی صفیں پھٹ پھٹ جاتی تھیں.جب اپنی خود کے ساتھ سرخ رومال
باند ھے ابودجانہ ان پر حملہ کرتا تھا اور اس تلوار کے ساتھ جو اسے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے دی
تھی چاروں طرف گویا موت
بکھیرتا جاتا تھا.حمزہ اپنے سر پر شتر مرغ کے پروں کی کلغی لہراتا ہوا
ہر جگہ نمایاں نظر آتا تھا.علی اپنے لمبے اور سفید پھر یرے کے ساتھ اور ز بیراپنی شوخ رنگ کی چمکتی
ہوئی زرد پگڑی کے ساتھ بہادر ان الیڈ کی طرح جہاں بھی جاتے تھے دشمن کے واسطے موت
و پریشانی کا پیغام اپنے ساتھ لے جاتے تھے.یہ وہ نظارے ہیں جہاں بعد کی اسلامی فتوحات
۲ ،،
کے ہیر و تربیت پذیر ہوئے.“.غرض لڑائی ہوئی اور بہت سخت ہوئی اور کافی وقت تک لبہ کا پہلو مشکوک رہا لیکن آخر خدا کے فضل
سے قریش کے پاؤں اکھڑنے لگے اور ان کے لشکر میں بدنظمی اور ابتری کے آثار ظاہر ہونے لگے.قریش
: ابن ہشام وزرقانی و نمیس
لائف آف محمد صفحه ۲۵۲،۲۵۱
Page 568
۵۵۳
کے علمبر دار ایک ایک کر کے مارے گئے اور ان میں سے تقریباً نو شخصوں نے باری باری اپنے قومی جھنڈے
کو اپنے ہاتھ میں لیا.مگر سارے کے سارے باری باری مسلمانوں کے ہاتھ سے
قتل ہوئے.آخر طلحہ کے
ایک حبشی غلام صواب نامی نے دلیری کے ساتھ بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لے لیا مگر اس پر بھی ایک مسلمان
نے آگے بڑھ کر وار کیا اور ایک ہی ضرب میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر قریش کا جھنڈا خاک پر گرا دیا
لیکن صواب کی بہادری اور جوش کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گرا اور جھنڈے کو اپنی
چھاتی کے ساتھ لگا کر اسے پھر بلند کرنے کی کوشش کی مگر اس مسلمان نے جو جھنڈے کے سرنگوں ہونے کی
قدر و قیمت کو جانتا تھا اوپر سے تلوار چلا کر صواب کو وہیں ڈھیر کر دیا.اس کے بعد پھر قریش میں سے کسی
شخص کو یہ جرات اور ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے علم کو اٹھائے یا ادھر مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا حکم پاکر تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر زور سے حملہ کیا اور دشمن کی رہی سہی صفوں کو چیرتے اور منتشر کرتے
ہوئے لشکر کے دوسرے پار قریش کی عورتوں تک پہنچ گئے اور مکہ کے لشکر میں سخت بھا گڑ پڑ گئی.اور دیکھتے
ہی دیکھتے میدان قریباً صاف ہو گیا.حتی کہ مسلمانوں کے لئے ایسی قابل اطمینان صورت حال پیدا ہوگئی
کہ وہ مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے ہے
جب عبد اللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنے امیر عبداللہ
سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور مسلمان غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں آپ ہم کو اجازت دیں کہ ہم بھی
لشکر کے ساتھ جاکر شامل ہو جائیں.عبداللہ نے انہیں روکا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی
ہدایت یاد دلائی، مگر وہ فتح کی خوشی میں غافل ہو رہے تھے اس لئے وہ باز نہ آئے.اور یہ کہتے ہوئے نیچے
اتر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ جب تک کہ پورا اطمینان نہ ہولے درہ خالی نہ
چھوڑا جاوے اور اب چونکہ فتح ہو چکی ہے اس لئے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سوائے عبد اللہ بن جبیر
اور ان کے پانچ سات ساتھیوں کے درہ کی حفاظت کے لئے کوئی نہ رہا.خالد بن ولید کی تیز آنکھ نے دور
سے درہ کی طرف دیکھا تو میدان صاف پایا جس پر اس نے اپنے سواروں کو جلدی جلدی جمع کر کے فوراً
درہ کا رخ کیا اور اس کے پیچھے پیچھے عکرمہ بن ابو جہل بھی رہے سہے دستہ کو ساتھ لے کر تیزی کے ساتھ
وہاں پہنچا اور یہ دونوں دستے عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن کی آن میں شہید کر کے
ا: ابن سعد
ابن ہشام
ے: طبری
: ابن سعد
بخاری حالات احد
: ابن سعد وزرقانی
Page 569
۵۵۴
اسلامی لشکر کے عقب میں اچانک حملہ آور ہو گئے.مسلمان جو فتح کے اطمینان میں غافل اور منتشر ہور ہے
تھے اس بلائے ناگہانی سے گھبرا گئے.مگر پھر بھی سنبھلے اور پلٹ کر کفار کے حملہ کو روکنا چاہا اس وقت کسی
چالاک معاند نے یہ آواز دی کہ اے مسلمانو! دوسری طرف سے بھی کفار کا دھاوا ہو گیا ہے.کے مسلمانوں نے
سراسیمہ ہوکر پھر پلٹا کھایا اور گھبراہٹ میں بے دیکھے سمجھے اپنے آدمیوں پر ہی تلوار چلانی شروع کر دی ہے
دوسری طرف مکہ کی ایک بہادر عورت عمرۃ بنت علقمہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو جھٹ آگے بڑھ کر قریش
کا علم جو ابھی تک خاک میں پڑا تھا اٹھا کر بلند کر دیا جسے دیکھتے ہی قریش کا منتشر لشکر پھر جمع ہو گیا."
اور اس طرح مسلمان حقیقتا چاروں طرف سے دشمن کے نرغہ میں گھر گئے اور اسلامی فوج میں ایک خطرناک
کھلبلی کی صورت پیدا ہوگئی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے یہ سب نظارہ
دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو آواز پر آواز دی مگر اس شور شرابے میں آپ کی آواز دب دب کر رہ جاتی تھی.مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتنے قلیل عرصہ میں ہو گیا کہ اکثر مسلمان بالکل بدحواس ہو گئے.حتی کہ اس
بدحواسی میں بعض مسلمان ایک دوسرے پر وار کرنے لگ گئے اور اپنے پرائے میں امتیاز نہ رہا.چنانچہ خود
مسلمانوں کے ہاتھ سے بعض مسلمان زخمی ہو گئے اور حذیفہ کے والد یمان کو تو مسلمانوں نے غلطی سے شہید
ہی کر دیا.حذیفہ اس وقت قریب ہی تھے وہ چلاتے رہ گئے کہ اے مسلمانو! یہ میرے والد ہیں مگر اس وقت
کون
سنتا تھا..آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مسلمانوں کی طرف سے یمان کا خون بہا ادا کرنا چاہا
مگر حذیفہ نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے باپ کا خون مسلمانوں کو معاف کرتا ہوں.حضرت حمزہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہونے کے علاوہ آپ کے رضاعی بھائی بھی
تھے.نہایت بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور جدھر جاتے تھے ان کے سامنے قریش کی صفیں پھٹ پھٹ
جاتی تھیں مگر دشمن بھی ان کی تاک میں تھا اور جبیر بن مطعم اپنے ایک حبشی غلام وحشی نامی کو خاص
طور پر آزادی کا وعدہ دے کر اپنے ساتھ لایا تھا کہ جس طرح بھی ہو حمزہ کو جنہوں نے جبیر کے چچا طعیمہ بن
عدی کو بدر کے موقع پر تلوار کی گھاٹ اتارا تھا قتل کر کے اس کے انتقام کو پورا کرے.چنانچہ وحشی ایک جگہ
پر چھپ کر ان کی تاک میں بیٹھ گیا اور جب حمزہ کسی شخص پر حملہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرے تو اس نے
بخاری کتاب المغازی حالات احد نیز ابن سعد
ابن سعد
زرقانی
ابن ہشام ۵ سورة آل عمران ۱۵۳ تا ۱۵۶ ۱ بخاری کتاب المغازی حالات احد
ے ابن ہشام : مسلم ابواب الرضاع
Page 570
خوب تاک کر ان کی ناف کے نیچے اپنا چھوٹا سا نیزہ مارا جو لگتے ہی بدن کے پار ہو گیا.حمزہ لڑکھڑاتے
ہوئے گرے مگر پھر ہمت کر کے اٹھے اور ایک جست کر کے وحشی کی طرف بڑھنا چاہا مگر پھر لڑ کھڑا کر گرے
اور جان دے دی اور اس طرح اسلامی لشکر کا ایک مضبوط باز وٹوٹ گیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
حمزہ کے قتل کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت صدمہ ہوا اور روایت آتی ہے کہ غزوہ طائف کے بعد جب حمزہ کا
قاتل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے معاف تو فرما دیا.مگر حمزہ کی محبت کا احترام
کرتے ہوئے فرمایا کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا کرے.اس وقت وحشی نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ
جس ہاتھ سے میں نے رسول خدا کے چا کو قتل کیا ہے.جب تک اس ہاتھ سے کسی بڑے دشمن اسلام کو تہ تیغ
نہ کرلوں گا چین نہ لوں گا.چنانچہ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں اس نے جنگ یمامہ میں نبوت کے
جھوٹے مدعی مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے اپنے عہد کو پورا کیا.اس گھمسان کے موقع پر وہ مسلمان عورتیں بھی
جو اس غزوہ میں ساتھ تھیں پوری تندہی اور جانفشانی سے اپنے کام میں مصروف تھیں اور ادھر ادھر بھاگ کر
صحابہ کو پانی پلانے اور زخمیوں کی خبر گیری کرنے اور اسی قسم کی دوسری خدمات سرانجام دے رہی تھیں.ان خواتین میں حضرت عائشہ اور ام سلیم اور ام سلیط کے اسماء صحابہ کو پانی لا لا کر پلانے کی خدمت کی ضمن
میں خاص طور پر مذکور ہوئے ہیں.کے
جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے یہ وقت مسلمانوں کے واسطے سخت پریشانی کا وقت تھا.قریش کے لشکر
نے قریباً چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے پے در پے حملوں سے ہر آن دباتا چلا آتا تھا.اس
پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سنجل جاتے مگر غضب یہ ہوا کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبد اللہ بن
قمئہ نے مسلمانوں کے علمبردار مصعب بن عمیر پر حملہ کیا اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا دایاں ہاتھ
کاٹ گرایا.مصعب نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور ابن قمئہ کے مقابلہ کے لئے آگے
بڑھے.مگر اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا.اس پر مصعب نے اپنے دونوں
کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے چھاتی سے
چمٹا لیا.جس پر ابن قمئہ نے ان پر تیسر اوار کیا اور اب کی دفعہ مصعب شہید ہو کر گر گئے.جھنڈا تو کسی
دوسرے مسلمان نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا.مگر چونکہ مصعب کا ڈیل ڈول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بخاری کتاب المغازی حالات احد
بخاری حالات غزوہ احد
بخاری کتاب المغازی حالات احد
زرقانی
Page 571
سے ملتا تھا ابن قمیہ نے سمجھا کہ میں نے
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو مار لیا ہے.یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی
طرف سے یہ تجویز محض شرارت اور دھوکا دہی کے خیال سے ہو.بہر حال اس نے مصعب کے شہید ہوکر
گرنے پر شور مچادیا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو مارلیا ہے.اس خبر سے مسلمانوں کے رہے
سہے اوسان بھی جاتے رہے.اور ان کی جمعیت بالکل منتشر ہوگئی اور بہت سے صحابی سراسمیہ ہو کر
میدان سے بھاگ نکلے.اس وقت مسلمان تین حصوں میں منقسم تھے.ایک گروہ وہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر یہ گروہ سب سے تھوڑا تھا.ان لوگوں میں حضرت عثمان
بن عفان بھی شامل تھے." مگر جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آتا ہے اس وقت کے خاص حالات اور ان
لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا.ان لوگوں میں
سے بعض مدینہ تک جا پہنچے اور اس طرح مدینہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی شہادت اور لشکر
اسلام کی ہزیمت کی خبر پہنچ گئی جس سے تمام شہر میں ایک کہرام مچ گیا اور مسلمان مرد، عورتیں بچے بوڑھے
نہایت سراسیمگی کی حالت میں شہر سے باہر نکل آئے اور احد کی طرف روانہ ہو گئے.اور بعض تو جلد جلد
دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے.دوسرے گروہ
میں وہ لوگ تھے جو بھاگے تو نہیں تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یا تو ہمت ہار
بیٹھے تھے اور یا اب لڑنے کو بریکار سمجھتے تھے اور اس لئے میدان سے ایک طرف ہٹ کر سرنگوں ہو کر بیٹھ گئے
تھے.تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا.ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے اردگرد جمع تھے اور بے نظیر جان نثاری کے جوہر دکھا رہے تھے اور اکثر وہ تھے جو میدان جنگ میں منتشر
طور پر لڑ رہے تھے.ان لوگوں اور نیز گروہ ثانی کے لوگوں کو جوں جوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
زندہ موجود ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا یہ لوگ دیوانوں کی طرح لڑتے بھڑتے آپ کے ارد گرد جمع ہوتے
جاتے تھے.اس وقت جنگ کی حالت یہ تھی کہ قریش کا لشکر گویا سمندر کی مہیب لہروں کی طرح چاروں
طرف سے بڑھا چلا آتا تھا اور میدان جنگ میں ہر طرف سے تیر اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی.جان شاروں نے اس خطرہ کی حالت کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال کر آپ کے جسم
ابن ہشام
زرقانی
زرقانی
بخاری حالات احد
۵: سورة آل عمران : ۱۵۶
زرقانی
Page 572
مبارک کو اپنے بدنوں سے چھپا لیا، مگر پھر بھی جب کبھی حملہ کی رو اٹھتی تھی تو یہ چند گنتی کے آدمی ادھر ادھر
دھکیل دئے جاتے تھے اور ایسی حالت میں بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اکیلے رہ جاتے
تھے.کسی ایسے ہی موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے مشرک بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا ایک پتھر آپ
کے چہرہ مبارک پر لگا.جس سے آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور ہونٹ بھی زخمی ہوا.ابھی زیادہ وقت
نہ گزرا تھا کہ ایک اور پتھر جو عبداللہ بن شہاب نے پھینکا تھا اس نے آپ کی پیشانی کو زخمی کیا اور تھوڑی
دیر کے بعد تیسرا پتھر جوا بن قمیہ نے پھینکا تھا آپ کے رخسار مبارک پر آکر لگا جس سے آپ کے مغفر (خود)
کی دو کڑیاں آپ کے رخسار میں چھ کر رہ گئیں.سعد بن ابی وقاص کو اپنے بھائی عقبہ کے اس فعل پر اس قدر
غصہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کبھی کسی دشمن کے قتل کے لئے اتنا جوش نہیں آیا جتنا مجھے اُحد کے دن
عتبہ کے قتل کا جوش تھا.اس وقت نہایت خطر ناک لڑائی ہورہی تھی اور مسلمانوں کے واسطے ایک سخت ابتلا اور امتحان کا وقت
تھا اور جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت سے صحابہ ہمت
ہار چکے تھے اور ہتھیار پھینک کر میدان سے ایک طرف ہو گئے تھے.انہی میں حضرت عمررؓ بھی تھے.چنانچہ یہ
لوگ اسی طرح میدان جنگ کے ایک طرف بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک صحابی انس بن نضر انصاری آگئے
اور ان
کو دیکھ کر کہنے لگے.” تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا.”رسول اللہ نے شہادت
پائی.اب لڑنے سے کیا حاصل ہے؟ انس نے کہا.یہی تو لڑنے کا وقت ہے تا جوموت رسول اللہ نے پائی
وہ ہمیں بھی نصیب ہو اور پھر آپ کے بعد زندگی کا بھی کیا لطف ہے؟ اور پھر ان کے سامنے سعد بن معاذ
آئے تو انہوں نے کہا.”سعد مجھے تو پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے.“ یہ کہ کر انس دشمن کی صفوں میں
گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے.جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر اسی سے زیادہ زخم تھے
اور کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ یہ کس کی لاش ہے.آخر ان کی بہن نے ان کی انگلی دیکھ کر شناخت کیا.جو صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے انہوں نے جو جان نثاریاں دکھائیں تاریخ ان کی
نظیر لانے سے عاجز ہے.یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد گھومتے تھے اور آپ کی خاطر اپنی
جان پر کھیل رہے تھے.جو وار بھی پڑتا تھا صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے
ابن ہشام
ابن ہشام وزرقانی
ے: طبری
: ابن ہشام
: بخاری حالات غزوه احد
Page 573
۵۵۸
تھے اور ساتھ ہی دشمن پر بھی وار کرتے جاتے تھے.حضرت علی اور زبیر نے بے تحاشا دشمن پر حملے کئے اور ان
کی صفوں کو دھکیل دھکیل دیا.ابوطلحہ انصاری نے تیر چلاتے چلاتے تین کمانیں توڑیں اور دشمن کے تیروں
کے مقابل پر سینہ سپر ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو اپنی ڈھال سے چھپایا.سعد بن وقاص
کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے جاتے تھے اور سعدیہ تیر دشمن پر بے تحاشا چلاتے جاتے
،،
تھے.ایک دفعہ آپ نے سعد سے فرمایا.” تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں برابر تیر چلاتے جاؤ.سعد
اپنی آخری عمر تک آپ کے ان الفاظ کو نہایت فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے.ابودجانہ نے بڑی
دیر تک آپ کے جسم کو اپنے جسم سے چھپائے رکھا اور جو تیر یا پتھر آتا تھا اسے اپنے جسم پر لیتے تھے.حتی کہ
ان کا بدن تیروں سے چھلنی ہو گیا، مگر انہوں نے اُف تک نہیں کی تا ایسا نہ ہو کہ ان کے بدن میں حرکت پیدا
ہونے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ نگا ہو جاوے اور آپ کو کوئی تیر آ لگے.طلحہ نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے کئی وارا اپنے بدن پر لئے اور اسی کوشش میں ان
کا ہاتھ شل ہو
کر ہمیشہ کے لئے بیکار ہو گیا.مگر یہ چند گنتی کے جاں نثار اس سیلاب عظیم کے سامنے کب تک ٹھہر سکتے
تھے جو ہر لحظہ مہیب موجوں کی طرح چاروں طرف سے بڑھتا چلا آتا تھا.دشمن کے ہر حملہ کی ہر ہر مسلمانوں
کو کہیں کا کہیں بہا کر لے جاتی تھی مگر جب ذرا زور تھمتا تھا مسلمان بیچارے لڑتے بھڑتے پھر اپنے محبوب
آقا کے گرد جمع ہو جاتے تھے.بعض اوقات تو ایسا خطرناک حملہ ہوتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عملاً
اکیلے رہ جاتے تھے.چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے ارد گر دصرف بارہ آدمی رہ گئے اور ایک وقت ایسا
تھا کہ آپ کے ساتھ صرف دو آدمی ہی رہ گئے.ان جان نثاروں میں حضرت ابو بکر علی ، طلحہ، زبیر سعد بن
وقاص، ابودجانہ انصاری، سعد بن معاذ اور طلحہ انصاری کے نام خاص طور پر مذکور ہوئے ہیں.ایک وقت
جب قریش کے حملہ کی ایک غیر معمولی لہر اٹھی تو آپ نے فرمایا.”کون ہے جو اس وقت اپنی جان خدا کے
رستے میں نثار کر دے ؟ ایک انصاری کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ اور چھے اور انصاری صحابی دیوانہ
وار آگے بڑھے اور ان میں سے ایک ایک نے آپ کے ارد گر دلڑتے ہوئے جان دے دی.اس پارٹی
کے رئیس زیاد بن سکن تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھاوے کے بعد حکم دیا کہ زیاد کو اٹھا
بخاری حالات احد
سے ابن ہشام وزرقانی
بخاری حالات غزوہ احد
بخاری حالات احد
بخاری کتاب المغازی باب اِذْهَمَّتْ طَائِفَتَان عن ابي عثمان
مسلم ذکر غزوہ احد
Page 574
۵۵۹
کر میرے پاس لاؤ.لوگ اٹھا کر لائے اور انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا.اس
وقت زیاد میں کچھ کچھ جان تھی ، مگر وہ دم تو ڑ رہے تھے.اس حالت میں انہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنا
سر اٹھایا اور اپنا منہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی لے
ایک مسلمان خاتون جس کا نام ام عمارہ تھا تلوار ہاتھ میں لے کر مارتی کامتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس پہنچی.اس وقت عبد اللہ بن قسمئة آپ پر وار کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا.مسلمان خاتون نے
جھٹ آگے بڑھ کر وہ وار اپنے اوپر لے لیا اور پھر تلوار تول کر اس پر اپنا وار کیا، مگر وہ ایک دوہری زرہ پہنے
ہوئے مرد تھا.اور یہ ایک کمز ور عورت.اس لئے وار کاری نہ پڑا.اور ابن قمئة دڑا تا ہوا اور مسلمانوں
کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور صحابہ کے روکتے روکتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا
اور پہنچتے ہی اس زور اور بے دردی کے ساتھ آپ کے چہرہ مبارک پر وار کیا کہ صحابہ کے دل دہل گئے.جاں نثار طلحہ نے لپک کر اپنے ننگے ہاتھ پر لیا، مگر ابن قسمئة کی تلوار ان کے ہاتھ کو قلم کرتی ہوئی آپ کے
پہلو پر پڑی.زخم تو خدا کے فضل سے نہ آیا کیونکہ آپ نے اوپر تلے دوزر ہیں پہنی ہوئی تھیں اور وار کا زور
بھی طلحہ کی جاں شاری سے کم ہو چکا تھا مگر اس صدمہ سے آپ چکر کھا کر نیچے گرے اور ابن قسمنة نے پھر
خوشی کا نعرہ لگایا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو مارلیا ہے.ابن قسمئة تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے خوشی کا نعرہ لگا تا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور اپنے زعم
میں یہ سمجھا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے ، مگر جو نہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرے
حضرت علی اور طلحہ نے فوراً آپ کو اوپر اٹھا لیا اور یہ معلوم کر کے مسلمانوں کے پژمردہ چہرے خوشی سے تمتما
اٹھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں.اب آہستہ آہستہ لڑائی کا زور بھی کم ہونا شروع
ہو گیا.کیونکہ ایک تو کفار اس اطمینان کی وجہ سے کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ محمد رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں
اور اس لئے انہوں نے لڑائی کی طرف سے توجہ ہٹا کر کچھ تو اپنے مقتولین کی دیکھ بھال اور کچھ مسلمان
شہیدوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کی طرف پھیر لی تھی.اور دوسری طرف مسلمان بھی اکثر منتشر ہو چکے
تھے.جب قریش ذرا پیچھے ہٹ گئے اور جو مسلمان میدان میں موجود تھے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو پہچان کر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تو آپ نے اپنے ان صحابہ کی جمعیت میں آہستہ آہستہ پہاڑ کے
ابن ہشام و طبری
: ابن سعد وابن ہشام
ابن ہشام
ابن ہشام
Page 575
۵۶۰
اوپر چڑھ کر ایک محفوظ درہ میں پہنچ گئے.راستہ میں مکہ کے ایک رئیس ابی بن خلف کی نظر آپ پر پڑی اور
وہ بغض و عداوت میں اندھا ہو کر یہ الفاظ پکارتا ہوا آپ کی طرف بھاگا کہ لَا نَجُوتُ إِنْ نَجَا اگر
محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) بچ کر نکل گیا تو گویا میں تو نہ بچا صحابہ نے اسے روکنا چاہا مگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا.اسے چھوڑ دو اور میرے قریب آنے دو.اور جب وہ آپ پر حملہ کرنے کے خیال سے
آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے ایک نیزہ لے کر اس پر ایک وار کیا جس سے وہ چکر کھا کر زمین پر گرا اور
پھر اٹھ کر چیختا چلاتا ہوا واپس بھاگ گیا اور گو بظاہر زخم زیادہ نہیں تھا مگر مکہ پہنچنے سے پہلے وہ پیوند خاک
ہو گیا." جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درہ میں پہنچ گئے تو قریش کے ایک دستے نے خالد بن ولید کی
کمان میں پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنا چاہا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے چند
مہاجرین کو ساتھ لے کر اس کا مقابلہ کیا اور اسے پسپا کر دیا.کے
درہ میں پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مدد سے اپنے زخم دھوئے اور جو دوکڑیاں
آپ کے رخسار میں چھ کر رہ گئی تھیں وہ ابو عبیدہ بن الجراح نے بڑی مشکل سے اپنے دانتوں کے ساتھ
کھینچ کھینچ کر باہر نکالیں حتی کہ اس کوشش میں ان کے دورانت بھی ٹوٹ گئے.اس وقت آپ کے زخموں
سے بہت خون بہہ رہا تھا.اور آپ اس خون کو دیکھ کر حسرت کے ساتھ فرماتے تھے.كَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ
خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَيَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ سے کس طرح نجات پائے گی وہ قوم جس نے
اپنے نبی کے منہ کو اس کے خون سے رنگ دیا.اس جرم میں کہ وہ انہیں خدا کی طرف بلاتا ہے.اس
کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا اللهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمُ
لَا يَعْلَمُونَ.یعنی اے میرے اللہ ! تو میری قوم کو معاف کر دے.کیونکہ ان سے یہ قصور جہالت اور
لاعلمی میں ہوا ہے.روایت آتی ہے کہ اسی موقع پر یہ قرآنی آیت نازل ہوئی کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ یعنی عذاب و عفو کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں خدا جسے چاہے گا
معاف کرے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا.فاطمۃ الزہرا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
وحشتناک خبریں سن کر مدینہ سے نکل آئی تھیں وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اُحد میں پہنچ گئیں اور آتے ہی
ابن ہشام و طبری
طبری وابن ہشام
بخاری حالات غزوه احد
: ابن سعد وابن ہشام : ابن ہشام
ه مسلم حالات احد نیز زرقانی جلد ۲ صفحه ۴۹
Page 576
۵۶۱
آپ کے زخموں کو دھونا شروع کر دیا ، مگر خون کسی طرح بند ہونے میں ہی نہیں آتا تھا.آخر حضرت
فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس کی خاک آپ کے زخم پر باندھی تب جا کر کہیں خون تھا.دوسری
خواتین نے بھی اس موقع پر زخمی صحابیوں کی خدمت کر کے ثواب حاصل کیا.ادھر مسلمان اپنی مرہم پٹی میں مصروف تھے تو اُدھر دوسری طرف یعنی نیچے میدان جنگ میں مکہ کے
قریش مسلمان شہیدوں کی نعشوں کی نہایت بے دردانہ طور پر بے حرمتی کر رہے تھے.مثلہ کی وحشیانہ رسم
پوری وحشت کے ساتھ ادا کی گئی اور مسلمان شہیدوں کی نعشوں کے ساتھ مکہ کے خونخوار درندوں نے جو کچھ
بھی ان کے دل میں آیا وہ کیا.قریش کی عورتوں نے مسلمانوں کے ناک کان کاٹ کر ان کے ہار پر وئے اور
پہنے.ابوسفیان کی بیوی ہند حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبا گئی.یا غرض بقول سرولیم میور مسلمانوں کی
نعشوں کے ساتھ قریش نے نہایت وحشیانہ سلوک کیا.اور مکہ کے رؤساء دیر تک آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی نعش میدان میں تلاش کرتے رہے اور اس نظارے کے شوق میں ان کی آنکھیں ترس گئیں
مگر جو چیز کہ نہ پانی تھی نہ پائی.اس تلاش سے مایوس ہو کر ابوسفیان اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لے کر اس
درہ کی طرف بڑھا جہاں مسلمان جمع تھے اور اس کے قریب کھڑے ہوکر پکار کر بولا.مسلمانو! کیا تم میں
محمد ہے ؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جواب نہ دے.چنانچہ سب صحابہ خاموش
رہے.پھر اس نے ابو بکر وعمر کا پوچھا، مگر اس پر بھی آپ کے ارشاد کے ماتحت کسی نے جواب نہ دیا.جس پر
اس نے بلند آواز سے فخر کے لہجہ میں کہا کہ یہ سب لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو جواب
دیتے.اس وقت حضرت عمر سے نہ رہا گیا اور وہ بے اختیار ہو کر بولے.اے عدو اللہ تو جھوٹ کہتا ہے ہم
سب زندہ ہیں اور خدا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ذلیل کرے گا.ابوسفیان نے حضرت عمر کی آواز پہچان
کر کہا.”عمر ! سچ سچ بتاؤ کیا محمد زندہ ہے؟ حضرت عمرؓ نے کہا.”ہاں ہاں ! خدا کے فضل سے وہ زندہ ہیں
اور تمہاری یہ باتیں سن رہے ہیں.ابوسفیان نے کسی قدر دھیمی آواز میں کہا.تو پھر ابن قسمئة نے جھوٹ
کہا ہے کیونکہ میں تمہیں اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں.اس کے بعد ابوسفیان نے نہایت بلند آواز سے پکار
کر کہا.اُعْلُ هُبل یعنی اے ھبل " تیری بلندی ہو.صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
بخاری کتاب المغازی حالات احد : ابن ہشام وطبری
بخاری کتاب المغازی حالات احد نیز کتاب الجہاد
1 : قریش کا ایک بڑا بت تھا
: لائف آف محمد
۵ : ابن ہشام
Page 577
۵۶۲
کا خیال کر کے خاموش رہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نام پر تو خاموش رہنے کا حکم دیتے تھے
اب خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں بت کا نام آنے پر بے تاب ہو گئے اور فرمایا تم جواب کیوں نہیں
دیتے ؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا جواب دیں.آپ نے فرمایا کہو اللهُ أَعْلَى وَاجَلٌ
یعنی بلندی اور بزرگی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے.ابوسفیان نے کہا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزّى
لَكُمُ.” ہمارے ساتھ عزی ہے.اور تمہارے ساتھ عربی نہیں ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے فرمایا کہو اللهُ مَوْلَنَا وَلَا مَوْلى لَكُمُ.عری کیا چیز ہے.”ہمارے ساتھ اللہ ہمارا مددگار ہے
اور تمہارے ساتھ کوئی مددگار نہیں.اس کے بعد ابوسفیان نے کہا.لڑائی ایک ڈول کی طرح ہوتی ہے جو
کبھی چڑھتا اور کبھی گرتا ہے.پس یہ دن بدر کے دن کا بدلہ سمجھو اور تم میدان جنگ میں ایسی لاشیں پاؤ
گے جن کے ساتھ مثلہ کیا گیا ہے.میں نے اس کا حکم نہیں دیا مگر جب مجھے اس کا علم ہوا تو مجھے اپنے آدمیوں
کا یہ فعل کچھ برا بھی نہیں لگا.اور ہمارے اور تمہارے درمیان آئندہ سال انہی ایام میں بدر کے
مقام میں پھر جنگ کا وعدہ رہا.ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت جواب دیا کہ
+ 66
،،
بہت اچھا.یہ وعدہ رہا.“
یہ کہہ کر ابوسفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر نیچے اتر گیا اور پھر جلد ہی لشکر قریش نے مکہ کی راہ لی.یہ ایک
عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش کو اس موقع پر مسلمانوں کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا اور ظاہری
اسباب کے لحاظ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی اس فتح سے فائدہ اٹھا سکتے تھے اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کا راستہ
تو بہر حال ان کے لئے کھلا تھا مگر خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ قریش کے دل باوجود اس فتح کے اندر ہی اندر
مرعوب تھے اور انہوں نے اسی غلبہ کو غنیمت جانتے ہوئے جو احد کے میدان میں ان کو حاصل ہوا تھا مکہ کو
جلدی جلدی لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا مگر بایں ہمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے خیال سے
فوراستر صحابہ کی ایک جماعت جس میں حضرت ابو بکر اور حضرت زبیر بھی شامل تھے تیار کر کے لشکر قریش
کے پیچھے روانہ کر دی ہے یہ بخاری کی روایت ہے.عام مؤرخین یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علیؓ
یا بعض روایات کی رو سے سعد بن وقاص کو قریش کے پیچھے بھجوایا اور ان سے فرمایا کہ اس بات کا پتہ لاؤ کہ
لشکر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا اور آپ نے ان سے فرمایا اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں
: ایک اور بت کا نام ہے
ابن ہشام
بخاری کتاب المغازی حالات احد
بخاری حالات غزوہ احد
Page 578
۵۶۳
اور گھوڑوں کو خالی چلا رہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکہ کی طرف واپس جارہے ہیں مدینہ پر حملہ آور ہونے کا
ارادہ نہیں رکھتے اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں تو سمجھنا ان کی نیت بخیر نہیں.اور آپ نے ان کو تاکید فرمائی
کہ اگر قریش کا لشکر مدینہ کا رخ کرے تو فوراً آپ کو اطلاع دی جاوے اور آپ نے بڑے جوش کی
حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینہ پر حملہ کیا تو خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس
حملہ کا مزا چکھا دیں گے.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمی آپ کے ارشاد کے ماتحت
گئے اور بہت جلد یہ خبر لے کر واپس آگئے کہ قریش کا لشکر مکہ کی طرف جا رہا ہے.اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان میں اُتر آئے ہوئے تھے اور شہداء کی نعشوں کی دیکھ بھال
شروع تھی.جو نظارہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے تھا وہ خون کے آنسور لانے والا تھا.ستر مسلمان خاک
وخون میں لتھڑے ہوئے میدان میں پڑے تھے اور عرب کی وحشیانہ رسم مثلہ کا مہیب نظارہ پیش کر رہے
تھے.ان مقتولین میں صرف چھ مہاجر تھے اور باقی سب انصار سے تعلق رکھتے تھے.قریش کے مقتولوں کی
تعداد تئیس تھی.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا اور رضاعی بھائی حمزہ بن عبدالمطلب کی نعش کے
پاس پہنچے تو بے خود سے ہو کر رہ گئے کیونکہ ظالم ہند زوجہ ابوسفیان نے اُن کی نعش کو بری طرح بگاڑا ہوا
تھا.تھوڑی دیر تک تو آپ خاموشی سے کھڑے رہے اور آپ کے چہرہ سے غم وغصہ کے آثار نمایاں تھے.ایک لمحہ کے لئے آپ کی طبیعت اس طرف بھی مائل ہوئی کہ مکہ کے ان وحشی درندوں کے ساتھ جب تک
انہی کا سا سلوک نہ کیا جائے گا وہ غالباً ہوش میں نہیں آئیں گے مگر آپ اس خیال سے رک گئے اور صبر کیا
بلکہ اس کے بعد آپ نے مثلہ کی رسم کو اسلام میں ہمیشہ کے لئے ممنوع قرار دیدیا اور فرمایا دشمن خواہ کچھ
کرے تم اس قسم کے وحشیانہ طریق سے بہر حال بازر ہو اور نیکی اور احسان کا طریق اختیار کرو آپ کی
پھوپھی صفیہ بنت عبدالمطلب اپنے بھائی حمزہ سے بہت محبت رکھتی تھیں.وہ بھی مسلمانوں کی ہزیمت کی
خبر سُن کر مدینہ سے نکل آئیں تھیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے صاحبزادے زبیر بن العوام
سے فرمایا کہ اپنی والدہ کو ماموں کی نعش نہ دکھانا مگر بہن کی محبت کب چھین لینے دیتی تھی.انھوں نے اصرار
کے ساتھ کہا کہ مجھے حمزہ کی نعش دکھا دو.میں وعدہ کرتی ہوں کہ صبر کروں گی اور کوئی جزع فزع کا کلمہ منہ
سے نہیں نکالوں گی ؛ چنانچہ وہ گئیں اور بھائی کی نعش دیکھ کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتی ہوئی
طبری وابن ہشام
: ابن سعد
بخاری حالات احد
: زرقانی
۵ : ابن ہشام وطبری
Page 579
۵۶۴
خاموش ہو گئیں لے قریش نے دوسرے صحابہ کی نعشوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا.چنانچہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جحش کی نعش کو بھی بُری طرح بگاڑا گیا تھا.جوں جوں
نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نغش سے ہٹ کر دوسری نعش کی طرف جاتے تھے آپ کے چہرہ پر غم والم
کے آثار زیادہ ہوتے جاتے تھے.غالباً اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ کوئی جا کر دیکھے کہ سعد بن الربیع رئیس
انصار کا کیا حال ہے آیا وہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ؟ کیونکہ میں نے لڑائی کے وقت دیکھا تھا کہ وہ دشمن کے
نیزوں میں بری طرح گھرے ہوئے تھے.آپ کے فرمانے پر ایک انصاری صحابی ابی بن کعب گئے
اور میدان میں ادھر ادھر سعد کو تلاش کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا.آخر انہوں نے اونچی اونچی آواز میں دینی شروع
کیں اور سعد کا نام لے لے کر پکارا مگر پھر بھی کوئی سراغ نہ ملا.مایوس ہوکر وہ واپس جانے کو تھے کہ
انہیں خیال آیا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو پکاروں شاید اس طرح پتہ چل جاوے.چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا.سعد بن ربیع کہاں ہیں مجھے رسول اللہ نے ان کی طرف
بھیجا ہے.اس آواز نے سعد کے نیم مردہ جسم میں ایک بجلی کی لہر دوڑا دی اور انہوں نے چونک کر مگر نہایت
دھیمی آواز میں جواب دیا.”کون ہے میں یہاں ہوں.“ ابی بن کعب نے غور سے دیکھا تو تھوڑے فاصلہ
پر مقتولین کے ایک ڈھیر میں سعد کو پایا جو اس وقت نزع کی حالت میں جان تو ڑ رہے تھے.ابی بن کعب
نے ان سے کہا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے بھیجا ہے کہ میں تمہاری حالت سے آپ کو
اطلاع دوں.سعد نے جواب دیا کہ رسول اللہ سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ خدا کے رسولوں کو جوان
کے متبعین کی قربانی اور اخلاص کی وجہ سے ثواب ملا کرتا ہے خدا آپ کو وہ ثواب سارے نبیوں سے بڑھ
چڑھ کر عطا فرمائے اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور میرے بھائی مسلمانوں
کو بھی میر اسلام پہنچانا اور
میری قوم سے کہنا کہ اگر تم میں زندگی کا دم ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی
تو خدا کے سامنے تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا.یہ کہہ کر سعد نے جان دے دی ہے
اُحد کے شہداء میں ایک صاحب مصعب بن عمیر تھے.یہ وہ سب سے پہلے مہاجر تھے جو مدینہ میں
اسلام کے مبلغ بن کر آئے تھے.زمانہ جاہلیت میں مصعب مکہ کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوش پوش
اور بانکے سمجھے جاتے تھے اور بڑے ناز و نعمت میں رہتے تھے.اسلام لانے کے بعد ان کی حالت بالکل
بدل گئی.چنانچہ روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے بدن پر ایک کپڑا دیکھا.ابن ہشام ہے : موطا کتاب الجہا دوز رقانی وابن ہشام
: اصابه حالات مصعب
Page 580
جس پر کئی پیوند لگے ہوئے تھے.آپ کو ان کا وہ پہلا زمانہ یاد آ گیا تو آپ چشم پر آب ہو گئے.اُحد میں
جب مصعب شہید ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے ان کے بدن کو چھپایا جاسکتا.پاؤں ڈھانکتے تھے تو سرنگا ہوجاتا تھا اور سرڈھانکتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے حکم سے سر کو کپڑے سے ڈھانک کر پاؤں کو گھاس سے چھپا دیا گیا.نعشوں کی دیکھ بھال کے بعد تکفین و تدفین کا کام شروع ہوا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ جو کپڑے شہداء کے بدن پر ہیں وہ اسی طرح رہنے دئے جائیں اور شہداء کو غسل بھی نہ دیا
جاوے.البتہ کسی کے پاس کفن کے لئے زائد کپڑا ہو تو وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر لپیٹ دیا
جاوے.نماز جنازہ بھی اس وقت ادا نہیں کی گئی.چنانچہ بغیر نسل دئے اور بغیر نماز جنازہ ادا کئے شہداء کو دفتا
دیا گیا.اور عموماً ایک ایک کپڑے میں دو دو صحابیوں کو اکٹھا کفنا کر ایک ہی قبر میں اکٹھا دفن کر دیا گیا.جس
صحابی کو قرآن شریف زیادہ آتا تھا اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت لحد میں اتارتے
ہوئے مقدم رکھا جاتا تھا.گو اس وقت نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی لیکن بعد میں زمانہ وفات کے قریب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر شہداء احد پر جنازہ کی نماز ادا کی اور بڑے درد دل سے ان کے
لئے دعا فرمائی آپ اُحد کے شہداء کو خاص محبت اور احترام سے دیکھتے تھے.ایک دفعہ آپ اُحد کے شہداء
کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا " یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کا میں شاہد ہوں.حضرت
ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم نے انہیں کی طرح اسلام قبول نہیں
کیا ؟ کیا ہم نے انہی کی طرح خدا کے رستے میں جہاد نہیں کیا ؟ آپ نے فرمایا ”ہاں ! لیکن مجھے کیا معلوم
ہے کہ میرے بعد تم کیا کیا کام کرو گے.اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے اور بہت روئے اور عرض کیا.یا رسول اللہ ! کیا ہم آپ کے بعد زندہ رہ سکیں گے.صحابہ بھی اُحد کے شہداء کی بڑی عزت کرتے
تھے اور اُحد کی یاد کو ایک مقدس چیز کے طور پر اپنے دلوں میں تازہ رکھتے تھے.چنانچہ ایک دفعہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبدالرحمن بن عوف کے سامنے افطاری کا کھانا آیا جو غالباً کسی قدر
پر تکلف تھا.اس پر انہیں اُحد کا زمانہ یاد آ گیا جب مسلمانوں کے پاس اپنے شہداء کو کفنانے کے لئے
کپڑا تک نہیں تھا اور وہ ان کے بدنوں کو چھپانے کے لئے گھاس کاٹ کاٹ کر ان پر لپیٹتے تھے اور اس یاد
ل ترندی ابواب الزہد
بخاری حالات احد
بخاری حالات احد ۵ : مؤطا امام مالک کتاب الجہاد
بخاری حالات غزوہ احد وزرقانی
Page 581
نے عبدالرحمن بن عوف کو ایسا بے چین کر دیا کہ وہ بے تاب ہوکر رونے لگ گئے اور کھانا چھوڑ کر اٹھ
کھڑے ہوئے حالانکہ وہ روزے سے تھے.لے
سارے انتظامات سے فارغ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کے قریب مدینہ کی طرف روانہ
ہوئے.راستہ میں عقیدت کیش دور دور تک آگے آئے ہوئے تھے.ایک انصاری عورت سخت گھبراہٹ کی
حالت میں گھر سے نکل کر اُحد کے راستہ پر آ رہی تھی کہ راستہ میں اسے وہ صحابی ملے جو اُحد سے واپس
آرہے تھے اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے.صحابہ نے اسے اطلاع دی کہ تمہارا باپ
اور بھائی اور خاوند سب اُحد میں شہید ہوئے.مخلص خاتون جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت
سننے کے لئے بے تاب ہو رہی تھی بے چین ہو کر بولی.مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے
کہا رسول اللہ تو خدا کے فضل سے بخیریت ہیں اور یہ تشریف لا رہے ہیں.جب اس کی نظر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے اختیار ہو کر بولی.كُلُّ مُصِيبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلُ.اگر آپ زندہ ہیں
تو پھر سب مصیبتیں بیچ ہیں.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے اور انصار کے گھروں کے پاس
سے گزرے تو گھر گھر سے رونے چلانے کی آواز آتی تھی اور عورتیں عرب کی قدیم رسم کے مطابق نوحہ
کر رہی تھیں.آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو مسلمانوں کی تکلیف کا خیال کر کے آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں.پھر آپ نے ان
کو تسلی دینے کے خیال سے فرمایا.لكِنُ حَمُزَةُ فَلَا بَوَا كِيَ لَهُ یعنی ہمارے چا اور
رضاعی بھائی حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں مگر کسی عورت نے اس طرح ان
کا ماتم نہیں کیا.رؤساء انصار سمجھے کہ
آپ شاید اس حسرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اس غریب الوطنی کی حالت میں حمزہ کو کوئی رونے والا نہیں.وہ فوراً اپنی عورتوں کے پاس گئے اور کہا کہ بس اپنے مردوں پر رونا بند کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے مکان پر جا کر حمزہ کا ماتم کرو ( اللہ اللہ ! اس غلط فہمی میں بھی کیا جذ بہ اخلاص مخفی تھا ) آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان پر ماتم کا شور سنا تو پوچھا یہ کیسا شور ہے؟ عرض کیا گیا انصار کی عورتیں حمزہ
کا نوحہ کرتی ہیں.آپ نے ان کی محبت کی قدر کرتے ہوئے ان کے واسطے دعائے خیر فرمائی لیکن ساتھ ہی
فرمایا کہ اس طرح نوحہ کرنا اسلام میں منع ہے..اور آئندہ کے لئے نوحہ کی رسم یعنی بین کرنا یا پیٹنا یا بال
نو چنا وغیر ذالک اسلام میں ممنوع قرار دے دی گئی.یہ ایک نوجوان صحابی آپ کے سامنے آئے اور آپ
بخاری حالات غزوہ احد
تاریخ خمیس
ترمذی وابن ماجہ بحوالہ زرقانی
ابن سعد
Page 582
۵۶۷
نے دیکھا کہ ان کا چہرہ اپنے باپ کی شہادت پر مغموم ہے.فرمایا جابر کیا میں تمہیں ایک خوشی کی خبر
سناؤں؟ جابر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ! آپ نے فرمایا جب تمہارے والد شہید ہوکر اللہ کے حضور پیش
ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بے حجاب ہو کر کلام فرمایا اور فرمایا کہ جو مانگنا چاہتے ہو مانگو.تمہارے باپ
نے عرض کیا، اے میرے اللہ ! تیری کسی نعمت کی کمی نہیں ہے لیکن خواہش ہے کہ پھر دنیا میں جاؤں اور
تیرے دین کے رستہ میں پھر جان دوں.خدا نے فرمایا ہم تمہاری اس خواہش کو بھی ضرور پورا کر دیتے
لیکن ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.یعنی کوئی مردہ پھر زندہ ہو کر اس دنیا میں نہیں
آسکتا.جابر کے والد نے کہا تو پھر میرے بھائیوں کو میری اطلاع دے دی جاوے تاکہ ان کی جہاد کی
رغبت ترقی کرے.اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ خدا کے رستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھا کرو
کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں.حضرت سعد بن معاذ رئیس
قبیلہ اوس نے اپنی بوڑھی والدہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا.آپ نے ان سے
ان کے لڑکے عمرو بن معاذ کی شہادت پر اظہار ہمدردی کیا.انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ
سلامت ہیں تو ہمیں کیا غم ہے.“
یہ رات مدینہ میں ایک سخت خوف کی رات تھی کیونکہ باوجود اس کے کہ بظاہر لشکر
غزوہ حمراء الاسد
قریش نے مکہ کی راہ لے لی تھی یہ اندیشہ تھا کہ ان کا یہ فعل مسلمانوں کو غافل
کرنے کی نیت سے نہ ہوا اور ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک لوٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں لہذا اس رات کو مدینہ
میں پہرہ کا انتظام کیا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا خصوصیت سے تمام رات صحابہ نے پہرہ
دیا.صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ اندیشہ محض خیالی نہ تھا کیونکہ فجر کی نماز سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ اطلاع پہنچی کہ قریش کا لشکر مدینہ سے چند میل جا کر ٹھہر گیا ہے اور رؤساء قریش میں یہ سرگرم بحث جاری
ہے کہ اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ مدینہ پر حملہ کر دیا جاوے اور بعض قریش ایک دوسرے
کو طعنہ دے رہے ہیں کہ نہ تم نے
محمد کو قتل کیا اور نہ مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا اور نہ ان کے مال ومتاع
پر قابض ہوئے بلکہ جب تم ان پر غالب آئے اور تمہیں یہ موقع ملا کہ تم ان کو ملیا میٹ کر دو تو تم انہیں یونہی
چھوڑ کر واپس چلے آئے تا کہ وہ پھر زور پکڑ جاویں.پس اب بھی موقع ہے واپس چلو اور مدینہ پر حملہ کر کے
مسلمانوں کی جڑ کاٹ دو.اس کے مقابل میں دوسرے یہ کہتے تھے کہ تمہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے اسے
ترمذی وابن ماجه بحوالہ زرقانی
تاریخ خمیس
: ابن سعد
Page 583
۵۶۸
غنیمت جانو اور مکہ واپس لوٹ چلو ایسا نہ ہو کہ یہ شہرت بھی کھو بیٹھو اور یہ فتح شکست کی صورت میں بدل
جاوے کیونکہ اب اگر تم لوگ واپس لوٹ کر مدینہ پر حملہ آور ہو گے تو یقینا مسلمان جان تو ڑ کر لڑیں گے
اور جو لوگ اُحد میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی میدان میں نکل آئیں گے یا مگر بالآخر جو شیلے لوگوں کی
رائے غالب آئی اور قریش مدینہ کی طرف لوٹنے کے لئے تیار ہو گئے." آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً اعلان فرمایا کہ مسلمان تیار ہو جائیں مگر ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا
کہ سوائے ان لوگوں کے جو اُحد میں شریک ہوئے تھے اور کوئی شخص ہمارے ساتھ نہ نکلے..چنانچہ اُحد کے
مجاہدین جن میں سے اکثر زخمی تھے اپنے زخموں کو باندھ کر اپنے آقا کے ساتھ ہو لئے اور لکھا ہے کہ اس
موقع پر مسلمان ایسی خوشی اور جوش کے ساتھ نکلے کہ جیسے کوئی فاتح لشکر فتح کے بعد دشمن کے تعاقب میں
نکلتا ہے.آٹھ میل کا فاصلہ طے کر کے آپ حمراء الاسد میں پہنچے." جہاں دو مسلمانوں کی نعشیں میدان
میں پڑی ہوئی پائی گئیں اور تحقیقات پر معلوم ہوا کہ یہ وہ جاسوس تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
قریش کے پیچھے روانہ کئے تھے مگر جنہیں قریش نے موقع پا کر تل کر دیا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان شہداء کو ایک قبر کھدوا کر اس میں اکٹھا دفن کر وا دیا.اور اب چونکہ شام ہو چکی تھی آپ نے یہیں
ڈ میرا ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میدان میں مختلف مقامات پر آگ روشن کر دی جاوے.چنانچہ دیکھتے ہی
دیکھتے حمراء الاسد کے میدان میں پانچ سو آ گئیں شعلہ زن ہو گئیں جو ہر دور سے دیکھنے والے کے دل کو
مرعوب کرتی تھیں.غالباً اسی موقع پر قبیلہ خزاعہ کا ایک مشرک رئیس معبد نامی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اُحد کے مقتولین کے متعلق اظہار ہمدردی کی اور پھر اپنے راستہ پر روانہ
ہو گیا.دوسرے دن جب وہ مقام روحاء میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ قریش کالشکر وہاں ڈیرا ڈالے
پڑا ہے.اور مدینہ کی طرف واپس چلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں.معبد فوراً ابوسفیان کے پاس گیا اور اسے
جا کر کہنے لگا کہ تم کیا کرنے لگے ہو.واللہ میں تو ابھی محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے لشکر کو حمراء الاسد میں
چھوڑ کر آیا ہوں اور ایسا با رعب لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا اور اُحد کی ہزیمت کی ندامت میں ان کو اتنا
جوش ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی بھسم کر جائیں گے.ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں پر معبد کی ان باتوں
سے ایسا رعب پڑا کہ وہ مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے فوراً مکہ کی طرف روانہ ہو گئے.ل : زرقانی و خمیس
ابن ہشام
ابن سعد
ه: ابن سعد
: ابن ہشام وابن سعد
طبری وابن ہشام
Page 584
۵۶۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر قریش کے اس طرح بھاگ نکلنے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے خدا
کا شکر کیا اور فرمایا کہ یہ خدا کا رعب ہے جو اس نے کفار کے دلوں پر مسلط کر دیا ہے.اس کے بعد آپ نے حمراء الاسد میں دو تین دن اور قیام فرمایا اور پھر پانچ دن کی غیر حاضری کے بعد
مدینہ میں واپس تشریف لے آئے.اس مہم میں قریش کے دو سپاہی جن میں سے ایک غدار اور دوسرا
جاسوس تھا مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوئے اور چونکہ قوانین جنگ کے ماتحت ان کی سزا قتل تھی ، اس لئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان
کو قتل کر دیا گیا.ان میں سے ایک مکہ کا مشہور شاعر ابــوعُـزّہ تھا
جو بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوا تھا اور پھر اس کے معافی مانگنے اور یہ وعدہ کرنے پر کہ وہ
پھر کبھی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لئے نہیں نکلے گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا فدیہ چھوڑ دیا
تھا، مگر وہ غداری کر کے پھر مسلمانوں کے خلاف شریک جنگ ہوا اور نہ صرف خود شریک ہوا بلکہ اس نے
اپنے اشتعال انگیز اشعار سے دوسروں کو بھی ابھارا.چونکہ ایسے آدمی کی غداری مسلمانوں کے لئے سخت
نقصان دہ ہو سکتی تھی.پس جب وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
کے قتل کئے جانے کا حکم دیا.ابو غزہ نے پھر پہلے کی طرح زبانی معافی سے رہائی حاصل کرنی چاہی
مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے انکار فرما دیا کہ لايُلدَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ
،،
وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ " یعنی مومن ایک سوراخ میں سے دو دفعہ نہیں کاٹا جاتا “ “ دوسرا قیدی معاویہ بن مغیرہ
تھا.یہ شخص حضرت عثمان بن عفان کے رشتہ داروں میں سے تھا، مگر سخت معاند اسلام تھا.جنگ اُحد
کے بعد وہ خفیہ خفیہ مدینہ کے گردونواح میں گھومتا رہا مگر صحابہ نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا.آپ نے اسے حضرت عثمان کی سفارش پر یہ وعدہ لے کر چھوڑ دیا کہ تین
دن کے اندراندر وہاں سے رخصت ہو جاوے والا اسے جاسوسی کی سزا میں قتل کر دیا جائے گا.معاویہ نے
وعدہ کیا کہ میں تین دن تک چلا جاؤں گا.مگر جب یہ میعاد گزرگئی تو پھر بھی وہ وہیں خفیہ خفیہ پھرتا ہوا پایا
گیا، جس پر اسے قتل کر دیا گیا.تاریخ میں یہ مذکور نہیں ہوا کہ اس کی نیت کیا تھی.مگر اس طرح خفیہ خفیہ
مدینہ کے علاقہ میں رہنا اور باوجود متنبہ کر دئے جانے کے مقررہ معیاد کے بعد بھی ٹھہرے رہنا ظاہر کرتا
ہے کہ وہ کسی خطرناک ارادے سے وہاں ٹھہرا ہوا تھا اور کوئی تعجب نہیں کہ وہ احد کے میدان میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ جانے پر پیچ و تاب کھا تا ہوا مدینہ میں آپ کے خلاف کوئی بدا رادہ لے کر آیا ہو
: زرقانی
ابن ہشام
ابن ہشام
Page 585
۵۷۰
اور یہود یا منافقین مدینہ کی سازش سے کوئی مخفی وار کرنا چاہتا ہو ، مگر خدا تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اور اس
کی تجویز کارگر نہ ہوئی.جنگ اُحد کے نتائج مستقل نتائج کے لحاظ سے تو جنگ احد کوکوئی خاص اہمیت حاصل نہیں اور بدر
کے مقابل میں یہ جنگ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ، لیکن وقتی طور پر ضرور اس جنگ
نے مسلمانوں کو بعض لحاظ سے نقصان پہنچایا.اول ان کے ستر آدمی اس جنگ میں شہید ہوئے جن میں سے
بعض اکابر صحابہ میں سے تھے اور زخمیوں کی تعداد تو بہت زیادہ تھی.دوسرے مدینہ کے یہود اور منافقین جو
جنگ بدر کے نتیجہ میں کچھ مرعوب ہو گئے تھے اب کچھ دلیر ہو گئے.بلکہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں
نے تو کھلم کھلا تمسخر اڑایا اور طعنے دئے یا تیسرے قریش مکہ کو بہت جرات ہو گئی اور انہوں نے اپنے دل
میں یہ سمجھ لیا کہ ہم نے نہ صرف بدر کا بدلہ اتار لیا ہے بلکہ آئندہ بھی جب کبھی جتھا بنا کر حملہ کریں گے
مسلمانوں کو زیر کر سکیں گے.چوتھے عام قبائل عرب نے بھی اُحد کے بعد زیادہ جرات سے سراٹھانا شروع
کر دیا.مگر باوجودان نقصانات کے یہ ایک بین حقیقت ہے کہ جو نقصان قریش کو جنگ بدر نے پہنچایا
تھا جنگ اُحد کی فتح اس کی تلافی نہیں کر سکتی تھی.جنگ بدر میں مکہ کے تمام وہ رؤساء جو درحقیقت قریش کی
قومی زندگی کی روح تھے ہلاک ہو گئے تھے اور جیسا کہ قرآن شریف بیان کرتا ہے اس قوم کی صحیح معنوں میں
جڑ کاٹ دی گئی تھی اور یہ سب کچھ ایک ایسی قوم کے ہاتھوں ہوا تھا جو ظاہری سامان کے لحاظ سے ان کے
مقابلہ میں بالکل حقیر تھی.اس کے مقابلہ میں بے شک مسلمانوں کو اُحد کے میدان میں نقصان پہنچا لیکن وہ
اس نقصان کے مقابلہ میں بالکل حقیر اور عارضی تھا جو بدر میں قریش کو پہنچا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جو اسلامی سوسائٹی کے مرکزی نقطہ تھے اور جو قریش کی معاندانہ کارروائیوں کا اصل نشانہ تھے خدا کے فضل
سے زندہ موجود تھے.اس کے علاوہ اکابر صحابہ بھی سوائے ایک دو کے سب کے سب سلامت تھے
اور پھر مسلمانوں کی یہ ہزیمت ایسی فوج کے مقابلہ میں تھی جو ان سے تعداد میں کئی گنے زیادہ اور سامان
حرب میں کئی گنے مضبوط تھی.پس مسلمانوں کے لئے بدر کی عظیم الشان فتح کے مقابلہ میں اُحد کی ہزیمت
ایک معمولی چیز تھی اور یہ نقصان بھی مسلمانوں کے لئے ایک لحاظ سے بہت مفید ثابت ہوا کیونکہ ان پر
یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہوگئی کہ رسول اللہ کے منشا اور ہدایت کے خلاف قدم زن ہونا کبھی بھی
موجب فلاح اور بہبودی نہیں ہو سکتا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ٹھہرنے کی رائے دی
: لائف آف محمد مصنفه سرولیم میور
: طبری
Page 586
۵۷۱
اور اس کی تائید میں اپنا ایک خواب بھی سنایا مگر انہوں نے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اُحد کے ایک درہ میں متعین فرمایا اور انتہائی تاکید فرمائی کہ خواہ کچھ ہو جاوے
اس جگہ کو نہ چھوڑ نا مگر وہ غنیمت کے خیال سے اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے اور گو یہ عملی کمزوری ایک
محمد ود طبقہ کی طرف سے ظاہر ہوئی تھی مگر چونکہ انسانی تمدن سب کو ایک لڑی میں پرو کر رکھتا ہے اس لئے
اس کمزوری کے نتیجہ میں نقصان سب نے اٹھایا جیسا کہ اگر کوئی فائدہ ہوتا تو وہ بھی سب اٹھاتے.پس اُحد
کی ہزیمت اگر ایک لحاظ سے موجب تکلیف تھی تو دوسری جہت سے وہ مسلمانوں کے لئے ایک مفید سبق بھی
بن گئی اور تکلیف ہونے کے لحاظ سے بھی وہ ایک محض عارضی روک تھی جو مسلمانوں کے راستے میں پیش آئی
اور اس کے بعد مسلمان اس سیلاب عظیم کی طرح جو کسی جگہ رک کر اور ٹھوکر کھا کر تیز ہو جاتا ہے.نہایت
سرعت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے گئے.قرآن شریف میں جنگ اُحد کا ذکر زیادہ تر
سورۃ آل عمران میں آتا ہے جہاں اس جنگ کے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مسلمانوں کو آئندہ کے
لئے بعض اصولی ہدا یتیں دی گئی ہیں.اسلامی قانون ورثه جنگ اُحد کے بیان میں سعد بن الربیع کی شہادت کا ذکر گزر چکا ہے.سعد ایک
متمول آدمی تھے اور اپنے قبیلہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے.ان کی کوئی نرینہ
اولاد نہ تھی صرف دولڑ کیاں تھیں اور بیوی تھی.چونکہ ابھی تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم ورثہ کے
متعلق کوئی جدید احکام نازل نہیں ہوئے تھے اور صحابہ میں قدیم دستور عرب کے مطابق ورثہ تقسیم ہوتا
تھا.یعنی متوفی کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اس کے جدی اقربا جائیداد پر قابض ہو جاتے تھے
اور بیوہ اورلڑکیاں یونہی خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں.اس لئے سعد بن الربیع کی شہادت پر ان کے بھائی نے
سارے ترکہ پر قبضہ کر لیا اور ان کی بیوہ اور لڑکیاں بالکل بے سہارا رہ گئیں.اس تکلیف سے پریشان ہوکر
سعد کی بیوہ اپنی دونوں لڑکیوں کو ساتھ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور
ساری سرگزشت سنا کر اپنی پریشانی کا ذکر کیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت صحیحہ کو اس درد کے قصہ
نے ایک ٹھیس لگائی مگر چونکہ ابھی تک اس معاملہ میں خدا کی طرف سے آپ پر کوئی احکام نازل نہیں ہوئے
تھے آپ نے فرمایا تم انتظار کرو پھر جو احکام خدا کی طرف سے نازل ہوں گے ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے
گا.چنانچہ آپ نے اس بارہ میں توجہ فرمائی اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آپ پر ورثہ کے معاملہ میں
ا : رکوع ۱۳ تا ۱۸
Page 587
۵۷۲
بعض وہ آیات نازل ہوئیں جو قرآن شریف کی سورۃ النساء میں بیان ہوئی ہیں.اس پر آپ نے سعد
کے بھائی کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ سعد کے ترکہ میں سے دو ثلث ان کی لڑکیوں اور ایک شمن اپنی بھاوج
کے سپر د کر دو اور جو باقی بچے وہ خود لے لو یے اور اس وقت سے تقسیم ورثہ کے متعلق جدید احکام کی ابتدا قائم
ہوگئی جس کی رو سے بیوی اپنے صاحب اولا د خاوند کے ترکہ میں آٹھویں حصہ کی اور بے اولا دخاوند کے
ترکہ میں چہارم حصہ کی اور لڑکی اپنے باپ کے ترکہ میں اپنے بھائی کے حصہ کی نسبت نصف حصہ کی اور
اگر بھائی نہ ہو تو سارے ترکہ میں سے حالات کے اختلاف کے ساتھ دو ثلث یا نصف کی اور ماں اپنے
صاحب اولا دلڑکے کے ترکہ میں چھٹے حصہ کی.اور بے اولا دلڑکے کے ترکہ میں تیسرے حصہ کی حق دار
قرار دی گئی اور اسی طرح دوسرے ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے..اور عورت کا وہ فطری حق جو اس سے
چھینا جا چکا تھا اسے واپس مل گیا.اس موقع پر یہ نوٹ کرنا غیر ضروری نہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی امتیازی خصوصیات
میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے طبقہ نسواں کے تمام جائز اور واجبی حقوق کی پوری پوری
حفاظت فرمائی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں گزرا
جس نے عورت کے حقوق کی ایسی حفاظت کی ہو جیسی آپ نے کی ہے.چنانچہ ورثہ میں ، بیاہ شادی میں،
خاوند بیوی کے تعلقات میں ، طلاق و خلع میں، اپنی ذاتی جائیداد پیدا کرنے کے حق میں، اپنی ذاتی جائیداد
کے استعمال کرنے کے حق میں تعلیم کے حقوق میں ، بچوں کی ولایت و تربیت کے حقوق میں ، قومی
اور ملکی معاملات میں حصہ لینے کے حق میں شخصی آزادی کے معاملہ میں، دینی حقوق اور ذمہ داریوں
میں.الغرض دین و دنیا کے ہر اس میدان میں جس میں عورت قدم رکھ سکتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کے تمام واجبی حقوق کو تسلیم کیا ہے اور اس کے حقوق کی حفاظت کو اپنی امت کے لئے ایک مقدس
امانت اور فرض کے طور پر قرار دیا ہے.یہی وجہ ہے کہ عرب کی عورت آپ کی بعثت کو اپنے لئے ایک
نجات کا پیغام مجھتی تھی.مجھے اپنے رستہ سے ہٹنا پڑتا ہے ورنہ میں بتاتا کہ عورت کے معاملہ میں آپ کی
تعلیم حقیقتاً اس اعلیٰ مقام پر قائم ہے جس تک دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی تمدن نہیں پہنچا اور یقینا آپ کا یہ
پیارا قول ایک گہری صداقت پر مبنی ہے کہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ
ل : رکوع ۲۱
: سورۃ نساء :۱۷۷
ترندی ابوداؤ د کتاب الفرائض وابن جرير سورة نساء
Page 588
۵۷۳
عَيْنِي فِي الصَّلواة ا یعنی ” دنیا کی چیزوں میں سے میری فطرت کو جن چیزوں کی محبت کا خمیر دیا گیا ہے
وہ عورت اور خوشبو ہیں مگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز یعنی عبادت الہی میں رکھی گئی ہے.شراب کی حرمت یہ بیان گزر چکا ہے کہ عرب میں شراب کثرت کے ساتھ پی جاتی تھی بلکہ شراب
نوشی عربوں کے قومی اخلاق کا ایک حصہ بن چکی تھی اور کوئی مجلس شراب کے بغیر
مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ خاص فیشن کے لوگوں میں شراب نوشی کے لئے خاص خاص اوقات مقرر تھے
جب وہ مجلسیں جما جما کر بدمستیاں کرتے تھے.گو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطری سعادت کے
ماتحت خود کبھی شراب نہیں پی اور نبوت سے قبل بھی اس بد عادت سے ہمیشہ مجتنب رہے اور بعض صحابہ بھی
ابتداء سے ہی تارک شراب تھے لیکن چونکہ اس وقت تک مذہبی طور پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لئے
صحابہ میں بہت سے لوگ شراب پیتے تھے اور بعض اوقات شراب نوشی کے بدنتائج بھی صحابہ میں رونما ہو
جاتے تھے.چنانچہ حدیث میں روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمز گانے شراب کے نشہ میں حضرت علیؓ
کے اونٹ ذبح کر دئیے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے کے لئے گئے تو انہوں نے آپ
کو بھی نہیں پہچانا اور آپ سے بے اعتنائی کی.اسی طرح روایت آتی ہے کہ ایک دعوت میں ایک صحابی
نے کسی قدر زیادہ شراب پی لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس کے بعد وہ نماز پڑھانے کے لئے اہل مجلس
کے امام بنے تو قرآت میں اصل آیت کی بجائے کچھ کا کچھ پڑھ گئے تے اس قسم کے واقعات کی وجہ سے
بعض صحابہ جن میں حضرت عمرؓ کا نام خاص طور پر مذکور ہوا ہے.اپنی جگہ پیچ و تاب کھاتے تھے کہ شراب نوشی
کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ ہونا چاہئے.لیکن گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عادت کو بہت مکروہ
اور ضرررساں سمجھتے تھے مگر چونکہ ابھی تک اس بارہ میں کوئی خدائی حکم نازل نہیں ہوا تھا ، اس لئے آپ
عملاً کچھ نہیں کر سکتے تھے.بالآخر غزوہ احد کے بعد ۳ ہجری کے آخر یا ۴ ہجری کے شروع میں خدائی وحی نازل ہوئی اور شراب
نوشی اسلام میں قطعی طور پر حرام قرار دے دی گئی.اس حرمت کے حکم کو صحابہ کرام نے جس انشراح اور رضا
کے ساتھ قبول کیا وہ اس روحانی اثر کی ایک بہت دلچسپ مثال ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک
نسائی و مسند احمد بروایت الجامع الصغیر سیوطی جلد اصفحه ۱۲۲
بخاری ابواب غزوہ بدر ومسلم کتاب الاشر به
: ابوداؤ د کتاب الاشربه
زرقانی حالات غزوہ اُحد
Page 589
۵۷۴
صحبت نے ان کے دلوں میں پیدا کیا تھا.حدیث میں انس بن مالک سے ایک روایت آتی ہے کہ جب
شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا اور پھر آپ نے ایک
صحابی سے
ارشاد فرمایا کہ وہ مدینہ کی گلی کوچوں میں چکر لگا کر اس کی منادی کر دیں.انس کہتے ہیں کہ اس
وقت میں ایک مکان میں ابوطلحہ انصاری اور بعض دوسرے صحابیوں کو شراب پلا رہا تھا.ہم نے اس منادی
کی آواز سنی تو ابوطلحہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو یہ شخص کیا منادی کر رہا ہے.میں نے پتہ لیا تو معلوم ہوا کہ
شراب حرام کر دی گئی ہے.جب میں نے واپس آکر اہل مجلس کو اس کی اطلاع دی تو اسے سنتے ہی ابوطلحہ
نے مجھ سے کہا.اٹھو اور شراب کے مٹکے زمین پر بہا دولے انس کہتے ہیں کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں
شراب بہتی ہوئی نظر آتی تھی.یے اور اسی باب کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص کی منادی سن کر
کسی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے تحقیق تو کر لو کہ یہ شخص سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ.بلکہ فوراً سب نے اپنے ہاتھ
کھینچ لئے اور شراب نوشی سے دفعتہ رک گئے - شراب نوشی کی سی عادت کو اور عادت بھی وہ جو گویا عرب
کی گھٹی میں تھی یکلخت ترک کر دینا اور ترک بھی ایسی حالت میں کرنا کہ شراب کا دور عملاً چل رہا ہو اور
پینے والے اس کے نشہ میں متوالے ہورہے ہوں ضبط نفس کی ایک ایسی شاندار مثال ہے جس کی نظیر تاریخ
عالم میں نہیں ملتی.یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ گوجیسا کہ بخاری کی بعض روایات میں اشارہ پایا جاتا ہے شراب کی قطعی
حرمت کا حکم غزوہ اُحد کے بعد نازل ہوا.مگر اس سے پہلے بھی بعض قرآنی آیات اس مضمون کی نازل
ہو چکی تھیں جن میں شراب کی برائی بیان کی گئی تھی.چنانچہ روایت آتی ہے کہ سب سے پہلے جو آیت
شراب کے بارے میں نازل ہوئی وہ یہ تھی کہ بے شک شراب میں بعض فوائد ہیں مگر اس کے نقصانات اس
کے فوائد پر غالب ہیں.ہے اس پر حضرت عمرؓ نے جنہیں شراب کے خلاف غالباً سارے صحابہ میں سے زیادہ
جوش تھا دعا کی کہ اے خدا! ہمیں شراب کے معاملہ میں کوئی زیادہ کھلا کھلا حکم عطا کر.جس پر یہ آیت نازل
ہوئی کہ اے مومنو! جب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز میں شامل نہ ہوا کرو.اس پر حضرت عمرؓ نے پھر یہی
دعا کی کہ خدایا کوئی قطعی حکم نازل فرما.جس پر بالآخر یہ آیت اتری کہ اے مسلمانو ! شراب اور جوا نا پاک
اور ضرر رساں افعال ہیں جن سے شیطان تمہارے اندر عداوت اور دشمنی پیدا کرنا چاہتا اور ان کے ذریعہ
بخاری تفسیر سورۃ مائده ومسلم کتاب الاشر به
بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ مائده
بخاری تفسیر سوره مائده
: سورة بقره : ۲۲۰ ۵ : سورة نساء : ۴۵
Page 590
۵۷۵
تمہیں خدا کے ذکر اور نماز سے غافل کرتا ہے پس تم ان چیزوں سے مجتنب رہو.جب یہ آیت اتری
تو مسلمانوں کی تسلی ہو گئی اور وہ شراب کو قطعی طور پر حرام سمجھ کر اس سے باز آ گئے." بلکہ اس کے بعد
انہیں شراب سے ایسی دوری پیدا ہو گئی کہ جو مسلمان ایسی حالت میں غزوہ اُحد میں شہید ہوئے تھے کہ انہوں
نے شراب پی ہوئی تھی انہیں ان شہداء کے متعلق بے چینی پیدا ہونے لگی کہ ان کا کیا حشر ہوگا ، جس پر یہ
آیت نازل ہوئی کہ حرمت سے پہلے پہلے لوگوں نے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی ملامت
نہیں.الغرض ۳ ہجری کے آخر یا ۴ ہجری کے شروع میں مگر بہر حال غزوہ اُحد کے بعد شراب نوشی اسلام
میں قطعی طور پر حرام ہوگئی اور شراب کی تعریف میں ہر وہ چیز شامل قرار دی گئی جو نشہ پیدا کرتی اور انسان کی
عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے.اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی جڑ پر تبر رکھ دیا جو
صحیح طور پر بدیوں کی ماں کہلاتی ہے.اس جگہ ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ از روئے عقل شراب نوشی کیسی ہے.قرآن نے
خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ شراب میں بعض فوائد بھی ہیں مگر یہ کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے
زیادہ ہیں اور اصولی طور پر انسانی عقل اس مسئلہ پر اس سے زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتی اور یہ ایک خوشی
کا مقام ہے کہ ہزاروں سالوں کے تلخ تجربات کے بعد آج دنیا اسی حقیقت کی طرف آرہی ہے جو اسلام
نے آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے آشکارا کی تھی اور ہر ملک میں شراب نوشی کے سدباب کے لئے
سوسائیٹیاں بن رہی ہیں بلکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں تو شراب کے خلاف ایک قانون بھی نافذ
ہو چکا ہے جس کی تقلید میں بعض دوسرے ممالک میں بھی تحریک شروع ہے.بنو اسد کی شرارت اور سر یہ ابوسلمہ محرم ۴ ہجری جنگ احد میں جو ہزیمت مسلمانوں کو پہنچی اس بنواسد سریہ
نے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف
سر اٹھانے پر آگے سے بھی زیادہ دلیر کر دیا.چنانچہ ابھی جنگ اُحد پر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور صحابہ ابھی
اپنے زخموں کے علاج سے بھی پوری طرح فارغ نہ ہوئے تھے کہ محرم ۴ ہجری میں اچانک آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ اطلاع پہنچی کہ قبیلہ اسد کا رئیس طلیحہ بن خویلد اور اس کا بھائی سلمہ بن خویلدا اپنے علاقہ
کے لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آمادہ کر رہے ہیں.اس خبر کے
ابوداؤ د کتاب الاشربه : بخاری تفسیر سوره مائده
ا: سورۃ مائده : ۹۱
بخاری ومسلم کتاب الاشر به : ابن سعد
Page 591
۵۷۶
ملتے ہی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ملک کے حالات کے ماتحت اس قسم کی خبروں کے خطرات
کو خوب سمجھتے تھے فوراً ڈیڑھ سو صحابیوں کا ایک تیز رودستہ تیار کر کے اس پر ابوسلمہ بن عبدالاسد کوامیر
مقر فرمایا اور انہیں تاکید کی کہ یلغار کرتے ہوئے پہنچیں اور پیشتر اس کے کہ بنو اسدا اپنی عداوت کو عملی جامہ
پہنا سکیں انہیں منتشر کر دیں.چنانچہ ابوسلمہ نے تیزی مگر خاموشی کے ساتھ بڑھتے ہوئے وسط عرب کے
مقام قطن میں بنواسد کو جالیا لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ بنو اسد کے لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہی ادھر ادھر
منتشر ہو گئے.اور ابوسلمہ چند دن کی غیر حاضری کے بعد مدینہ میں واپس پہنچ گئے.اس سفر کی غیر معمولی
مشقت سے ابوسلمہ کا وہ زخم جو انہیں اُحد میں آیا تھا اور اب بظاہر مندمل ہو چکا تھا پھر خراب ہو گیا اور باوجود
علاج معالجہ کے بگڑتا ہی گیا اور بالآخر اسی بیماری میں اس مخلص اور پرانے صحابی نے جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے وفات پائی نے بنو اسد کا رئیس طلیحہ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے بعد میں
مسلمان ہو گیا لیکن پھر مرتد ہو گیا بلکہ نبوت کا جھوٹا مدعی بن گرفتنہ وفساد کا موجب بنا مگر بالآخر شکست
کھا کر عرب سے بھاگ گیا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ تائب ہوا اور آخر کئی اسلامی جنگوں میں حصہ
لے کر اسلام پر وفات پا گیا.بنواھیان کی شرارت اور سفیان کا قتل محرم ۴ ہجری قریش کی اشتعال انگیزی اور احد میں
مسلمانوں کی وقتی ہزیمت اب نہایت
سرعت کے ساتھ اپنے خطرناک نتائج ظاہر کر رہی تھی.چنانچہ انہی ایام میں جن میں بنو اسد نے مدینہ
پر چھا پہ مارنے کی تیاری کی تھی.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بولیان کے لوگ اپنے سردار
سفیان بن خالد کی انگیخت پر اپنے وطن عرنہ میں جو مکہ سے قریب ایک مقام تھا ایک بہت بڑ الشکر جمع کر رہے
ہیں اور ان کا ارادہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہایت موقع شناس
اور مختلف قبائل عرب کی حالت اور ان کے رؤساء کی طاقت واثر سے خوب واقف تھے اس خبر کے موصول
ہوتے ہی سمجھ لیا کہ یہ ساری شرارت اور فتنہ انگیزی بنو لحیان کے رئیس سفیان بن خالد کی ہے اور اگر اس کا
وجود درمیان میں نہ رہے تو بنو لحیان مدینہ پر حملہ آور ہونے کی جرات نہیں کر سکتے اور یہ بھی آپ جانتے تھے
کہ سفیان کے بغیر اس قبیلہ میں فی الحال کوئی ایسا صاحب اثر شخص نہیں ہے جو اس قسم کی تحریک کا لیڈر بن
ل : ابن سعد وزرقانی
: اصابہ حالات ابو سلمہ
سے زرقانی حالات سریہ ابوسلمہ واصا به حالات طلیحہ بن خویلد : ابن سعد وزرقانی
Page 592
۵۷۷
سکے.لہذا یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر بنو لحیان کے خلاف کوئی فوجی دستہ روانہ کیا گیا تو غریب مسلمانوں
کے واسطے موجب تکلیف ہونے کے علاوہ ممکن ہے کہ یہ طریق ملک میں زیادہ کشت وخون کا دروازہ کھول
دے.آپ نے یہ تجویز فرمائی کہ کوئی ایک شخص چلا جائے اور موقع پا کر اس فتنہ کے بانی مبانی اور اس
شرارت کی جڑ سفیان بن خالد کو قتل کر دے.چنانچہ آپ نے اس غرض سے
عبداللہ بن انیس انصاری کو
روانہ فرمایا.اور چونکہ عبداللہ نے کبھی سفیان کو دیکھا نہیں تھا اس لئے آپ نے خودان کو سفیان کا سارا
حلیہ وغیرہ سمجھا دیا اور آخر میں فرمایا کہ ہوشیار رہنا، سفیان ایک مجسم شیطان ہے.چنانچہ عبداللہ بن انیس
نہایت ہوشیاری کے ساتھ بنو لحیان کے کیمپ میں پہنچے ( جو واقعی مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری میں بڑی
سرگرمی سے مصروف تھے ) اور رات کے وقت موقع پاکر سفیان کا خاتمہ کر دیا.بنو لحیان کو اس کا علم ہوا تو
انہوں نے عبد اللہ کا تعاقب کیا مگر وہ چھپتے چھپاتے ہوئے بیچ کر نکل آئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے جب عبداللہ بن انیس آئے تو آپ نے ان کی شکل دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ کامیاب ہو کر آئے
ہیں.چنانچہ آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا افلَحَ الْوَجْهُ یہ چہرہ تو با مرا دنظر آتا ہے.عبداللہ نے عرض کیا
اور کیا خوب عرض کیا ”أَفْلَحَ وَجْهُكَ يَارَسُوْلَ اللهِ “ یارسول اللہ سب کامیابی آپ کی ہے.“‘اس
وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا عصا عبداللہ کو بطور انعام کے عطا فر مایا اور فرمایا یہ عصا
تمہیں جنت میں ٹیک لگانے کا کام دے گا.عبداللہ نے یہ مبارک عصا نہایت محبت واخلاص کے ساتھ
اپنے پاس رکھا اور مرتے ہوئے وصیت کی کہ اسے ان کے ساتھ دفن کر دیا جائے.چنانچہ ایسا ہی کیا گیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی سے جس کا اظہار آپ نے عبداللہ کی بامراد واپسی پر فرمایا اور اس
انعام سے جو انہیں غیر معمولی طور پر عطا فرمایا پتہ لگتا ہے کہ آپ سفیان بن خالد کی فتنہ انگیزی کو نہایت
خطر ناک خیال فرماتے تھے اور اس کے قتل کو امن عامہ کے لئے ایک موجب رحمت سمجھتے تھے.کفار کی غداری اور واقعہ رجمیع صفر ۴ ہجری یہ دن مسلمانوں کے لئے سخت خطرہ کے دن تھے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف
ابن سعد وزرقانی
"
: سفیان بن خالد کے قتل کا واقعہ ابن ہشام میں بھی ہے، مگر ابن ہشام نے اسے تاریخ کی تعین کے بغیر اپنی سیرۃ کے
آخر میں بیان کیا ہے نیز ابن ہشام نے مقتول کا نام بجائے سفیان بن خالد کے خالد بن سفیان لکھا ہے باقی تفصیل
عملاً وہی ہے دیکھوا بن ہشام جلد ۳ صفحه ۸۳
Page 593
۵۷۸
سے متوحش خبریں آرہی تھیں لیکن سب سے زیادہ خطرہ آپ کو قریش مکہ کی طرف سے تھا جو جنگ اُحد کی
وجہ سے بہت دلیر اور شوخ ہورہے تھے اس خطرہ کو محسوس کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صفر ۴ ہجری
میں اپنے دس صحابیوں کی ایک پارٹی تیار کی اور ان پر عاصم بن ثابت کو امیر مقرر فر مایا اور ان کو یہ حکم دیا کہ
وہ خفیہ خفیہ مکہ کے قریب جا کر قریش کے حالات دریافت کریں اور ان کی کارروائیوں اور ارادوں سے
آپ کو اطلاع دیں.لیکن ابھی یہ پارٹی روانہ نہیں ہوئی تھی کہ قبائل عضل اور قارة کے چند لوگ آپ کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبائل میں بہت سے آدمی اسلام کی طرف مائل ہیں
آپ چند آدمی ہمارے ساتھ روانہ فرمائیں جو ہمیں مسلمان بنا ئیں اور اسلام کی تعلیم دیں.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش معلوم کر کے خوش ہوئے اور وہی پارٹی جو خبر رسانی کے لئے تیار کی گئی تھی
ان کے ساتھ روانہ فرما دی تے لیکن دراصل جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ لوگ جھوٹے تھے اور بنولحیان کی
انگیخت پر مدینہ میں آئے تھے جنہوں نے اپنے ریکس سفیان بن خالد کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے یہ چال چلی
تھی کہ اس بہانہ سے مسلمان مدینہ سے نکلیں تو ان پر حملہ کر دیا جاوے اور بنولحیان نے اس خدمت کے
معاوضہ میں عضل اور قارہ کے لوگوں کے لئے بہت سے اونٹ انعام کے طور پر مقرر کئے تھے.جب عضل
اور قارہ کے یہ غدار لوگ عسفان اور مکہ کے درمیان پہنچے تو انہوں نے بنو لحیان کو خفیہ خفیہ اطلاع بھجوا دی کہ
مسلمان ہمارے ساتھ آرہے ہیں تم آجاؤ.جس پر قبیلہ بنولحیان کے دوسونو جوان جن میں سے ایک سو
تیرانداز تھے مسلمانوں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور مقام رجیع میں ان کو آدبایا.دس آدمی
دوسوسپاہیوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے لیکن مسلمانوں کو ہتھیار ڈالنے کی تعلیم نہیں دی گئی تھی.فوراً یہ صحابی
ایک قریب کے ٹیلہ پر چڑھ کر مقابلہ کے واسطے تیار ہو گئے.کفار نے جن کے نزدیک دھوکا دینا کوئی
معیوب فعل نہیں تھا ان کو آواز دی کہ تم پہاڑی پر سے نیچے اتر آؤ ہم تم سے پختہ عہد کرتے ہیں کہ تمہیں قتل
نہیں کریں گے.عاصم نے جواب دیا کہ ”ہمیں تمہارے عہد و پیمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہم تمہاری اس
ذمہ داری پر نہیں اتر سکتے.اور پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا.”اے خدا! تو ہماری حالت کو دیکھ رہا
ہے.اپنے رسول کو ہماری اس حالت سے اطلاع پہنچا دے.غرض عاصم اور اس کے ساتھیوں نے مقابلہ
بخاری کتاب الجہاد باب هل يستامر الرجل وكتاب المغازی حالات رجیع و فتح الباری جلد ۲ صفحه ۲۹۱
: ابن ہشام وابن سعد
واقدی حالات واقعہ رجیع وزرقانی
۳: زرقانی جلد ۲ صفحه ۶۵
Page 594
۵۷۹
کیا بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہوئے.جب سات صحا بہ مارے گئے اور صرف خبیب بن عدی اور زید بن دشنہ اور ایک اور صحابی باقی رہ گئے
تو کفار نے جن کی اصل خواہش ان لوگوں کو زندہ پکڑنے کی تھی.پھر آواز دے کر کہا کہ اب بھی نیچے اتر
آؤ.ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے.اب کی دفعہ یہ سادہ لوح مسلمان ان کے
پھندے میں آکر نیچے آتر آئے ، مگر نیچے اترتے ہی کفار نے ان کو اپنی تیر کمانوں کی تندیوں سے جکڑ کر
باندھ لیا اور اس پر خبیب اور زید کے ساتھی سے جن کا نام تاریخ میں عبداللہ بن طارق مذکور ہوا ہے صبر
نہ ہوسکا اور انہوں نے پکار کر کہا.یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے.اور نہ معلوم تم آگے چل کر کیا کرو گے
اور عبداللہ نے ان کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا.جس پر کفار تھوڑی دور تک تو عبد اللہ کو گھسیٹتے ہوئے اور
زدو کوب کرتے ہوئے لے گئے اور پھر انہیں قتل کر کے وہیں پھینک دیا اور چونکہ اب ان کا انتقام پورا
ہو چکا تھا.وہ قریش کو خوش کرنے کے لئے نیز روپے کی لالچ سے خبیب اور زید کو ساتھ لے کر مکہ کی
طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر انہیں قریش کے ہاتھ فروخت کر دیا.چنانچہ خبیب کو تو حارث بن
عامر بن نوفل کے لڑکوں نے خرید لیا کیونکہ خبیب نے بدر کی جنگ میں حارث کو قتل کیا تھا.اور زید کو
صفوان بن امیہ نے خرید لیا.ابھی یہ دونوں صحابی قریش کے پاس غلامی کی حالت میں قید تھے کہ ایک دن حبیب نے حارث کی ایک
لڑکی سے اپنی ضرورت کے لئے ایک استرا مانگا اور اس نے دے دیا.جب یہ استر اخبیب کے ہاتھ میں تھا
تو بنت حارث کا ایک خوردسالہ بچہ کھیلتا ہوا خبیب کے پاس آ گیا اور خبیب نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا.ماں نے جب دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور ران پر اس کا بچہ بیٹھا ہے تو وہ کانپ اٹھی اور اس
کے چہرہ کا رنگ فق ہو گیا.خبیب نے اسے دیکھا تو اس کے خوف کو سمجھتے ہوئے کہا ” کیا تم یہ خیال
کرتی ہو کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ یہ خیال نہ کرو.میں انشاء اللہ ایسا نہیں کروں گا.”ماں کا کملایا ہوا
چہرہ خبیب کے ان الفاظ سے شگفتہ ہو گیا.یہ عورت خبیب کے اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر تھی کہ وہ
بعد میں ہمیشہ کہا کرتی کہ ” میں نے خبیب کا سا اچھا قیدی کوئی نہیں دیکھا.وہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ ”میں
نے ایک دفعہ حبیب کے ہاتھ میں ایک انگور کا خوشہ دیکھا تھا جس سے وہ انگور کے دانے توڑ تو ڑ کر کھاتا تھا
بخاری کتاب المغازی حالات رجیع نیز کتاب الجہاد
بخاری
: ابن ہشام وابن سعد
Page 595
۵۸۰
حالانکہ ان دنوں میں مکہ میں انگوروں کا نام ونشان نہیں تھا اور خبیب آہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا.وہ کہتی
تھی کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدائی رزق تھا جو خبیب کے پاس آتا تھا.مگر رؤسائے قریش کی قلبی عداوت کے سامنے رحم و انصاف کا جذ بہ خارج از سوال تھا.چنانچہ
ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بنو الحارث کے لوگ اور دوسرے رؤساء قریش خبیب کو قتل کرنے اور
اس کے قتل پر جشن منانے کے لئے اسے ایک کھلے میدان میں لے گئے.خبیب نے شہادت کی بو پائی تو
قریش سے نہایت الحاح کے ساتھ کہا کہ مرنے سے پہلے مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو.قریش نے جو
غالباً اسلامی نماز کے منظر کو بھی اس تماشہ کا حصہ بنانا چاہتے تھے اجازت دے دی اور خبیب نے بڑی توجہ
اور حضور قلب کے ساتھ دورکعت نماز ادا کی اور پھر نماز سے فارغ ہو کر قریش سے کہا کہ میرا دل چاہتا تھا
کہ میں اپنی نماز کو اور لمبا کروں لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں موت کو پیچھے
ڈالنے کے لئے نماز کو لمبا کر رہا ہوں اور پھر خبیب یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے جھک گئے.وَمَا اَنْ أُبَالِى حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِمًا
عَلى أَي شِيِّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِى
وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الا لَهِ وَإِنْ يَشَاء
يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شَلْوِ مُمَزَّعِ
یعنی ” جبکہ میں اسلام کی راہ میں اور مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جارہا ہوں تو مجھے یہ پروانہیں
ہے کہ میں کس پہلو پر قتل ہو کر گروں.یہ سب کچھ خدا کے لئے ہے.اور اگر میرا خدا چاہے گا تو میرے جسم
کے پارہ پارہ ٹکڑوں پر برکات نازل فرمائے گا.غالباً ابھی خبیب کی زبان پر ان اشعار کے آخری الفاظ
گونج ہی رہے تھے کہ عقبہ بن حارث نے آگے بڑھ کر وار کیا اور یہ عاشق رسول خاک پر تھا.دوسری
روایت میں یہ ہے کہ قریش نے خبیب کو ایک درخت کی شاخ سے لٹکا دیا تھا اور پھر نیزوں کی چوکیں دے
دے کر قتل کیا.اس مجمع میں ایک شخص سعید بن عامر بھی شریک تھا.یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا اور حضرت
عمر کے زمانہ خلافت تک اس کا یہ حال تھا کہ جب کبھی اسے خبیب
کا واقعہ یاد آتا تھا تو اس پر غشی کی حالت
طاری ہو جاتی تھی.بخاری کتاب الجہا دو کتاب المغازی
ابن ہشام
بخاری کتاب المغازی و کتاب الجہاد
Page 596
۵۸۱
دوسری طرف صفوان بن امیہ اپنے قیدی زید بن دشتہ کو ساتھ لے کر حرم سے باہر گیا.رؤساء قریش کا
ایک مجمع ساتھ تھا.باہر پہنچ کر صفوان نے اپنے غلام نسطاس کو حکم دیا کہ زید کو قتل کر دو.نسطاس نے آگے
بڑھ کر تلوار اٹھائی.اس وقت ابوسفیان بن حرب رئیس مکہ نے جو تماشائیوں میں موجود تھا آگے بڑھ کر زید
سے کہا.سچ کہو کیا تمہارا دل یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت تمہاری جگہ ہمارے ہاتھوں میں محمد ہوتا جسے ہم
قتل کرتے اور تم بچ جاتے اور اپنے اہل وعیال میں خوشی کے دن گزارتے ؟ زید کی آنکھوں میں خون
اتر آیا اور وہ غصہ میں بولے.ابوسفیان تم یہ کیا کہتے ہو.خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ میرے
بچنے کے عوض رسول اللہ کے پاؤں میں ایک کانٹا تک چھے.ابوسفیان بے اختیار ہوکر بولا.واللہ
میں نے کسی شخص کو کسی شخص کے ساتھ ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی کہ اصحاب محمد کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )
سے ہے.اس کے بعد نسطاس نے زید کو شہید کر دیا ہے
اسی واقعہ رجیع کی ضمن میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ جب قریش مکہ کو یہ اطلاع ملی کہ جولوگ بنولحیان
کے ہاتھ سے رجیع میں شہید ہوئے تھے ان میں عاصم بن ثابت بھی تھے.تو چونکہ عاصم نے بدر کے موقع
پر قریش کے ایک بڑے رئیس کو قتل کیا تھا ، اس لئے انہوں نے رجیع کی طرف خاص آدمی روانہ کئے اور ان
آدمیوں
کو تاکید کی کہ عاصم کا سر یا جسم کا کوئی عضو کاٹ کر اپنے ساتھ لائیں تا کہ انہیں تسلی ہو اور ان کا جذبہ
انتقام تسکین پائے.ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کو عاصم نے قتل کیا تھا اس کی ماں نے یہ نذر
مانی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پئے گی یے لیکن خدائی تصرف ایسا ہوا کہ یہ
لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زنبوروں اور شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کے جھنڈ عاصم کی لاش پر ڈیرہ
ڈالے بیٹھے ہیں اور کسی طرح وہاں سے اٹھنے میں نہیں آتے.ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ زنبور
اور مکھیاں وہاں سے اڑ جائیں مگر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی.آخر مجبور ہوکر یہ لوگ خائب و خاسر
واپس لوٹ گئے." اس کے بعد جلد ہی بارش کا ایک طوفان آیا اور عاصم کی لاش کو وہاں سے بہا کر کہیں کا
کہیں لے گیا.لکھا ہے کہ عاصم نے مسلمان ہونے پر یہ عہد کیا تھا کہ آئندہ وہ ہر قسم کی مشرکانہ چیز سے قطعی
پر ہیز کریں گے حتی کہ مشرک کے ساتھ چھوئیں گے بھی نہیں.حضرت عمرؓ کو جب ان کی شہادت اور اس
واقعہ کی اطلاع ہوئی تو کہنے لگے.خدا بھی اپنے بندوں کے جذبات کی کتنی پاسداری فرماتا ہے موت کے
ا : ابن ہشام وابن سعد
: فتح الباری جلد ے صفحہ ۲۹۵
بخاری حالات رجیع
بخاری حالات رجیع و فتح الباری جلد ۲ صفحه ۲۹۵
Page 597
۵۸۲
بعد بھی اس نے عاصم کے عہد کو پورا کر وایا اور مشرکین کے مس سے انہیں محفوظ رکھا.واقعہ رجیع کی خبر سے جو صدمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو پہنچ سکتا تھا وہ
ظاہر ہے مگر پیشتر اس کے کہ یہ المناک خبر مدینہ میں پہنچتی ایک اور خطرناک واقعہ پیش آگیا.اس لئے قبل
اس کے کہ ہم واقعہ رجیع کے متعلق کوئی تبصرہ کریں اس واقعہ کا بیان کر دینا ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں
واقعات ایک ہی نوعیت کے تھے اور ان کی اطلاع بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وقت میں
موصول ہوئی تھی.واقعہ بئر معونہ صفر ہجری قبائل سلیم و غطفان وغیرہ کی شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کا ذکر و پرگزر چکا
ہے یہ قبائل عرب کے وسط میں سطح مرتفع نجد پر آباد تھے اور مسلمانوں کے
خلاف قریش مکہ کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے اور آہستہ آہستہ ان شریر قبائل کی شرارت بڑھتی جاتی تھی
اور سارا سطح مرتفع نجد اسلام کی عداوت کے زہر سے مسموم ہوتا چلا جارہا تھا.چنانچہ ان ایام میں جن کا ہم
اس وقت ذکر کر رہے ہیں ایک شخص ابو براء عامری جو وسط عرب کے قبیلہ بنو عامر کا ایک رئیس تھا، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لئے حاضر ہوا.آپ نے بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے
اسلام
کی تبلیغ فرمائی اور اس نے بھی بظاہر شوق اور توجہ کے ساتھ آپ کی تقریر کو سنا ،مگر مسلمان نہیں ہوا.البتہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ اپنے چند اصحاب نجد کی طرف
روانہ فرما ئیں جو وہاں جا کر اہل نجد میں اسلام کی تبلیغ کریں اور مجھے امید ہے کہ نجدی لوگ آپ کی دعوت کو
رد نہیں کریں گے.آپ نے فرمایا مجھے تو اہل نجد پر اعتماد نہیں ہے.ابو براء نے کہا کہ آپ ہر گز فکر نہ کریں.میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہوں.چونکہ ابو براء ایک قبیلہ کا رئیس اور صاحب اثر آدمی تھا آپ نے
اس کے اطمینان دلانے پر یقین کر لیا اور صحابہ کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرما دی ہے
یہ تاریخ کی روایت ہے.بخاری میں آتا ہے کہ قبائل رعل اور ذکوان وغیرہ (جو مشہور قبیلہ بنوسلیم کی
شاخ تھے ) ان کے چند لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کر
کے درخواست کی کہ ہماری قوم میں سے جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہماری امداد کے لئے
یہ تشریح نہیں کی کہ کس قسم کی امداد، آیا تبلیغی یا فوجی چند آدمی روانہ کئے جائیں.جس پر آپ نے یہ
ابن ہشام
: ابن ہشام وابن سعد
زرقانی جلد ۲ صفحہ ۷۹ آخر حالات بئر معونہ
Page 598
۵۸۳
دسته روانہ فرمایا.اور اس کی تائید میں ابن سعد نے بھی ایک روایت نقل کی ہے گوا سے دوسری روایت کے
مقابل میں ترجیح نہیں دی.یا مگر بد قسمتی سے بئر معونہ کی تفصیلات میں بخاری کی روایات میں بھی کچھ خلط
واقع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے حقیقت پوری طرح متعین نہیں ہو سکتی.تا مگر بہر حال اس قدر یقینی طور پر
معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قبائل رعل اور ذکوان وغیرہ کے لوگ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں آئے تھے اور انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ چند صحابہ ان کے ساتھ بھجوائے جائیں.ان دونوں روایتوں کی مطابقت کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ رعل اور ذکوان کے لوگوں کے ساتھ ابوبراء
عامری رئیس قبیلہ عامر بھی آیا ہو اس نے ان کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی
ہو.چنانچہ تاریخی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے
اطمینان نہیں ہے اور پھر اس کا یہ جواب دینا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں میں اس کا ضامن ہوتا ہوں کہ
آپ کے صحابہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابو براء کے ساتھ رعل اور
ذ کو ان کے لوگ بھی آئے تھے جن کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے.واللہ اعلم
بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفرہ ہجری میں منذر بن عمر و انصاری کی امارت میں صحابہ کی
ایک پارٹی روانہ فرمائی ہے یہ لوگ عموماً انصار میں سے تھے اور تعداد میں ستر تھے اور قریباً سارے کے
سارے قاری یعنی قرآن خوان تھے جو دن کے وقت جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے ان کی قیمت پر اپنا پیٹ
پالتے اور رات کا بہت سا حصہ عبادت میں گزار دیتے تھے.جب یہ لوگ اس مقام پر پہنچے جو ایک کنوئیں
کی وجہ سے بئر معونہ کے نام سے مشہور تھا تو ان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جوانس بن مالک کے
ماموں تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس اور
ابو براء عامری کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس آگے گئے اور باقی صحابہ پیچھے رہے.جب حرام بن ملحان
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایچی کے طور پر عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو
انہوں نے شروع میں تو منافقانہ طور پر آؤ بھگت کی لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور اسلام کی تبلیغ
کرنے لگے تو ان میں سے بعض شریروں نے کسی آدمی کو اشارہ کر کے اس بے گناہ ایلچی کو پیچھے کی
بخاری کتاب الجہاد باب العون بالمدد و کتاب المغازی ابواب رجیع و بئر معونہ روایت عن قتاده عن انس
: ابن سعد جلد ۲ صفحه ۳۸
: ابن سعد وابن ہشام
فتح الباری جلد کے صفحہ ۳۰۱،۲۹۶ شرح حالات بئر معونہ
بخاری کتاب الجہاد باب العون بالمدد
Page 599
۵۸۴
طرف سے نیزہ کا وار کر کے وہیں ڈھیر کر دیا.اس وقت حرام بن ملحان کی زبان پر یہ الفاظ تھے.اللَّهُ أَكْبَرُ
فُرْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ یعنی اللہ اکبر کعبہ کے رب کی قسم ! میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا.عامر بن طفیل
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے قتل پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اس کے بعد اپنے قبیلہ بنو عامر کے
لوگوں کو اکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر حملہ آور ہو جائیں مگر انہوں نے اس بات سے انکار کیا
اور کہا کہ ہم ابو براء کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے.اس پر عامر نے
قبیلہ سلیم میں سے بنور عل اور ذکوان اور عصیہ وغیرہ کو ( وہی جو بخاری کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بن کر آئے تھے ) اپنے ساتھ لیا اور یہ سب لوگ مسلمانوں کی اس قلیل اور بے بس
جماعت پر حملہ آور ہو گئے.مسلمانوں نے جب ان وحشی درندوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان سے کہا
کہ ہمیں تم سے کوئی تعرض نہیں ہے.ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لئے آئے
ہیں اور ہم تم سے لڑنے کے لئے نہیں آئے.مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا.ان صحابیوں میں سے جو اس وقت وہاں موجود تھے صرف ایک شخص بچا جو پاؤں سے لنگڑا تھا اور پہاڑی
کے اوپر چڑھ گیا ہوا تھا.اس صحابی کا نام کعب بن زید تھا اور بعض روایات سے پتہ لگتا ہے کہ کفار نے
اس پر بھی حملہ کیا تھا جس سے وہ زخمی ہوا اور کفار سے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے مگر دراصل اس میں جان باقی
تھی اور وہ بچ گیا.صحابہ کی اس جماعت میں سے دو شخص یعنی عمرو بن امیہ ضمری اور منذر بن محمد اس وقت اونٹوں وغیرہ
کے چرانے کے لئے اپنی جماعت سے الگ ہو کر ادھر ادھر گئے ہوئے تھے انہوں نے دور سے اپنے ڈیرہ کی
طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں.وہ ان صحرائی
اشاروں کو خوب سمجھتے تھے.فورا تاڑ گئے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے.واپس آئے تو ظالم کفار کے کشت و خون
کا کارنامہ آنکھوں کے سامنے تھا.دور سے ہی یہ نظارہ دیکھ کر انہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کیا کہ اب
ہمیں کیا کرنا چاہئے.ایک نے کہا کہ ہمیں یہاں سے فور ابھاگ نکلنا چاہئے اور مدینہ میں پہنچ کر آنحضرت
بخاری کتاب الجہاد باب من ينكب او يطعن وكتاب المغازی ابواب رجیع و بئر معونہ روایت ابی طلحہ عن انس
وروایت عبداللہ بن انس وروایت عروۃ مخلوطاً
: ابن ہشام وابن سعد
بخاری ابواب حالات بئر معونہ روایت عبدالعزیز بعن انس
بخاری ابواب بئر معونہ روایت ابوطلحہ عن انس ۵ : ابن ہشام و ابن سعد
Page 600
۵۸۵
صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینی چاہئے.مگر دوسرے نے اس رائے کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں تو اس جگہ سے
بھاگ کر نہیں جاؤں گا جہاں ہمارا امیر منذر بن عمر و شہید ہوا ہے.چنانچہ وہ آگے بڑھ کر لڑا اور شہید ہوا.لے
اور دوسرے کو جس کا نام عمرو بن امیہ ضمری تھا کفار نے پکڑ کر قید کر لیا.اور غالبا اسے بھی قتل کر دیتے مگر
جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ مضر سے ہے تو عامر بن طفیل نے عرب کے دستور کے مطابق اس کے ماتھے
کے چند بال کاٹ کر اسے رہا کر دیا اور کہا کہ میری ماں نے قبیلہ مضر کے ایک غلام کے آزاد کرنے کی منت
مانی ہوئی ہے میں تجھے اس کے بدلے میں چھوڑتا ہوں.گویا ان ستر صحابہ میں صرف دو شخص بچے.ایک یہی
عمر و بن امیہ ضمری اور دوسرے کعب بن زید جسے کفار نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا.کے
بئر معونہ کے موقع پر شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام اور اسلام کے
دیرینہ فدائی عامر بن فہیرہ بھی تھے.انہیں ایک شخص جبار بن سلمی نے قتل کیا تھا.جبار بعد میں مسلمان
ہو گیا اور وہ اپنے مسلمان ہونے کی وجہ یہ بیان کرتا تھا کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کو شہید کیا تو ان کے
منہ سے بے اختیار نکلا فزت واللہ یعنی ” خدا کی قسم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں.“ جبار کہتے ہیں کہ
میں یہ الفاظ سن کر سخت متعجب ہوا کہ میں نے تو اس شخص کو قتل کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مراد کو پہنچ گیا
ہوں یہ کیا بات ہے.چنانچہ میں نے بعد میں لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے معلوم ہوا کہ مسلمان
لوگ خدا کے رستے میں جان دینے کو سب سے بڑی کامیابی خیال کرتے ہیں اور اس بات کا میری طبیعت
پر ایسا اثر ہوا کہ آخر اسی اثر کے ماتحت میں مسلمان ہو گیا.3
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو واقعہ رجیع اور واقعہ بئر معونہ کی اطلاع قریباً ایک ہی
وقت میں ملی.اور آپ کو اس کا سخت صدمہ ہوا.حتی کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایسا صدمہ نہ اس
پہلے آپ کو کبھی ہوا تھا اور نہ بعد میں کبھی ہوا کے واقعی قریباً اسی صحابیوں کا اس طرح دھو کے کے
ساتھ اچانک مارا جانا اور صحابی بھی وہ جو اکثر حفاظ قرآن میں سے تھے اور ایک غریب بے نفس طبقہ سے
تعلق رکھتے تھے.عرب کے وحشیانہ رسم ورواج کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اور خود
ނ
بخاری حالات بئر معونہ روایت ہشام بن عروة عن عروة
ابن ہشام
ابن ہشام
بخاری حالات بئر معونہ روایت عائشہ ۵ : زرقانی جلد ۲ صفحه ۷۸
ابن ہشام حالات بئر معونہ واسد الغابہ حالات جبار بن سلمی
کے زرقانی
بخاری کتاب الجہاد باب دعاء الامام علی من نکث
دس رجیع کے اور ستر بئر معونہ کے
Page 601
۵۸۶
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو یہ خبر گویا اسی بیٹوں کی وفات کی خبر کے مترادف تھی بلکہ اس سے بھی
بڑھ کر کیونکہ ایک روحانی انسان کے لئے روحانی رشتہ یقیناً اس سے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے جتنا کہ
ایک دنیا دار شخص کو دنیا وی رشتہ عزیز ہوتا ہے.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حادثات کا سخت
صدمہ ہوا مگر اسلام میں بہر صورت صبر کا حکم ہے آپ نے یہ خبرسن کر إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا
اور پھر یہ الفاظ فرماتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ هَذَا عَمَلُ اَبِي بَرَّاءَ وَقَدْ كُنْتُ لِهَذَا كَارِهَا
مُتَخَوّفًا یعنی یہ ابو براء کے کام کا ثمرہ ہے ورنہ میں تو ان لوگوں کے بھجوانے کو پسند نہیں کرتا تھا اور
اہل نجد کی طرف سے ڈرتا تھا.واقعات بئر معونہ اور رجیع سے قبائل عرب کے اس انتہائی درجہ کے بغض و عداوت کا پتہ چلتا ہے جو
وہ اسلام اور متبعین اسلام کے متعلق اپنے دلوں میں رکھتے تھے.حتیٰ کہ ان لوگوں کو اسلام کے خلاف ذلیل
ترین قسم کے جھوٹ اور دغا اور فریب سے بھی کوئی پر ہیز نہیں تھا اور مسلمان با وجود اپنی کمال ہوشیاری اور
بیدار مغزی کے بعض اوقات اپنی مومنانہ حسن ظنی میں ان کے دام کا شکار ہو جاتے تھے.حفاظ قرآن،
نماز گزار، تہجد خوان، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کا نام لینے والے اور پھر غریب مفلس فاقوں کے
مارے ہوئے یہ وہ لوگ تھے جن کو ان ظالموں نے دین سیکھنے کے بہانے سے اپنے وطن میں بلایا اور پھر
جب مہمان کی حیثیت میں وہ ان کے وطن میں پہنچے تو ان کو نہایت بے رحمی کے ساتھ تہ تیغ کر دیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا جتنا بھی صدمہ ہوتا کم تھا مگر اس وقت آپ نے رجیع اور بئر معونہ
کے خونی قاتلوں کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں فرمائی.البتہ اس خبر کے آنے کی تاریخ سے لے کر برابر
تمیں دن تک آپ نے ہر روز صبح کی نماز کے قیام میں نہایت گریہ زاری کے ساتھ قبائل رعل اور ذکوان
اور عصیہ اور بنو لحیان کا نام لے لے کر خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی اے میرے آقا تو ہماری حالت پر رحم فرما
اور دشمنان اسلام کے ہاتھ کو روک جو تیرے دین کو مٹانے کے لئے اس بے رحمی اور سنگدلی کے ساتھ
بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں."
ابن ہشام
بخاری ابواب بئر معونہ روایت ابوطلحه عن انس
Page 602
۵۸۷
یہود کی دوسری غداری.جمع و ترتیب قرآن
حضرت زینب کی شادی.واقعہ افک
اور منافقین کی فتنہ پردازی
اخراج بنو نضیر.ربیع الاول ۴ ہجری جب کسی قوم کے برے دن آتے ہیں تو پھر اس کی بینائی کم بنونضیر
ہو جاتی ہے اور واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی
طرف وہ توجہ نہیں کرتی.چنانچہ بنو قینقاع کے جلاوطن کئے جانے پر بجائے اس کے کہ یہود کے باقی ماندہ
دو قبیلے عبرت حاصل کرتے اور اپنی شرارتوں
اور فتنہ انگیزیوں سے باز آ جاتے اور مسلمانوں کو امن کی زندگی
بسر کرنے دیتے اور خود بھی امن کے ساتھ رہتے انہوں نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف
اندر ہی اندر فتنے کے شرارے پیدا کرتے رہے اور قریش مکہ کے ساتھ بھی ان لوگوں نے برابر ساز باز رکھی
بلکہ بنو قینقاع کے بعد ان کی عداوت اور بھی ترقی کر گئی اور ان کے منصوبے دن بدن زیادہ خطرناک صورت
اختیار کرتے گئے.چنانچہ ابھی واقعات رجیع اور بئر معونہ پر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حالات نے ایسی
نازک صورت اختیار کرلی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حفاظتی کے خیال سے مجبور ہوکر بنونضیر کے
خلاف فوج کشی کرنی پڑی جس کے نتیجہ میں بالآخر یہ قبیلہ بھی مدینہ سے جلاوطن ہو گیا.اس غزوہ کا سبب
بیان کرتے ہوئے ارباب حدیث وسیر مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے اس
غزوہ کے زمانہ کے متعلق بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے.ابن اسحاق اور ابن سعد جن کی اتباع میں نے اس
جگہ بلا کسی خاص تحقیق کے اختیار کی ہے غزوہ بنو نضیر کو غزوہ اُحد اور واقعہ بئر معونہ کے بعد بیان کرتے ہیں
اور اس کا سبب یہ لکھتے ہیں کہ عمرو بن امیہ ضمری جنہیں کفار نے بئر معونہ کے موقع پر قید کر کے چھوڑ دیا
Page 603
۵۸۸
تھا.وہ جب واپس مدینہ کی طرف آرہے تھے تو انہیں راستہ میں قبیلہ بنو عامر کے دو آدمی ملے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، چونکہ عمرو کو اس عہد و پیمان کا علم نہیں تھا اس لئے اس نے
موقع پاکر ان دو آدمیوں کو شہداء بئر معونہ کے بدلے میں قتل کر دیا جن کے قتل کا باعث قبیلہ بنو عامر کا ایک
رئیس عامر بن طفیل ہوا تھا.گو جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے خود قبیلہ بنو عامر کے لوگ اس قتل وغارت سے
دست کش رہے تھے.جب عمرو بن امیہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا
عرض کیا اور ان دو آدمیوں کے قتل کا واقعہ بھی سنایا.آپ کو جب ان دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع ہوئی تو
آپ عمرو بن امیہ کے اس فعل پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ وہ تو ہمارے معاہد تھے.اور آپ نے فوراً
ان ہر دو مقتولین کا خون بہا ان کے ورثاء کو بھجوا دیا ، لیکن چونکہ قبیلہ بنو عامر کے لوگ بنو نضیر کے بھی
حلیف تھے اور بنو نضیر مسلمانوں کے حلیف تھے اس لئے معاہدہ کی رو سے اس خون بہا کا بارحصہ رسدی بنو
نفیر پر بھی پڑتا تھا.چنانچہ آپ اپنے چند صحابیوں کو ساتھ لے کر بنونضیر کی آبادی میں پہنچے اور ان سے یہ
سارا واقعہ بیان کر کے خون بہا کا حصہ مانگا.انہوں نے بظاہر آپ کے تشریف لانے پر خوشی کا اظہار کیا اور
کہا کہ آپ تشریف رکھیں ہم ابھی اپنے حصہ کا رو پید ادا کئے دیتے ہیں.چنانچہ آپ مع اپنے چند اصحاب
کے ایک دیوار کے سایہ میں بیٹھ گئے اور بنو نضیر باہم مشورہ کے لئے ایک طرف ہو گئے اور ظاہر یہ کیا کہ ہم
روپے کی فراہمی کا انتظام کر رہے ہیں لیکن بجائے روپے کا انتظام کرنے کے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یہ
ایک بہت ہی اچھا موقع ہے.محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) مکان کے سایہ میں دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں کوئی
شخص دوسری طرف سے مکان پر چڑھ جاوے اور پھر ایک بڑا پتھر آپ کے اوپر گرا کر آپ کا کام تمام
کر دے یا یہود میں سے ایک شخص سلام بن مشکم نے اس تجویز کی مخالفت کی.اور کہا کہ یہ ایک غداری
کا فعل ہے اور اس عہد کے خلاف ہے جو ہم لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ کر چکے ہیں مگر ان لوگوں
نے نہ مانا اور بالآخر عمر و بن حجاش نامی ایک یہودی ایک بہت بھاری پتھر لے کر مکان کے اوپر چڑھ گیا
اور قریب تھا کہ وہ اس پتھر کو اوپر سے لڑھکا دیتا مگر روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ
نے یہود کے اس بد ارادے سے بذریعہ وحی اطلاع دے دی اور آپ جلدی سے وہاں سے اٹھ آئے اور
ایسی جلدی میں اٹھے کہ آپ کے اصحاب نے بھی اور یہود نے بھی یہ سمجھا کہ شاید آپ کسی حاجت کے
خیال سے اٹھ گئے ہیں.چنانچہ وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کرتے رہے، لیکن آپ
لے: ابن ہشام وابن سعد
: ابن سعد
Page 604
۵۸۹
وہاں سے اٹھ کر سیدھے مدینہ میں تشریف لے آئے.صحابہ نے تھوڑی دیر آپ کا انتظار کیا لیکن جب
آپ واپس تشریف نہ لائے تو وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھے اور آپ کو ادھر ادھر تلاش کرتے ہوئے بالآخر
خود بھی مدینہ پہنچ گئے.اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہود کی اس خطرناک سازش کی
اطلاع دی.اور پھر قبیلہ اوس کے ایک رئیس محمد بن مسلمہ کو بلا کر فرمایا کہ تم بنونضیر کے پاس جاؤ اوران
کے ساتھ اس معاملہ کے متعلق بات چیت کرو اور ان سے کہو کہ چونکہ وہ اپنی شرارتوں میں بہت بڑھ گئے
ہیں اور ان کی غداری انتہا کو پہنچ گئی ہے اس لئے اب انکا مدینہ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے.بہتر ہے کہ وہ
مدینہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں اور آپ نے ان کے لئے دس دن کی معیاد مقررفرمائی.محمد بن مسلمہ جب ان کے پاس گئے تو وہ سامنے سے بڑے تمز د سے پیش آئے اور کہا کہ محمد ( صلی اللہ
علیہ وسلم ) سے کہہ دو کہ ہم مدینہ سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہیں تم نے جو کرنا ہوکر لو.جب ان کا یہ
جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا.اللہ اکبر یہود تو جنگ کے لئے تیار
بیٹھے ہیں.اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور صحابہ کی ایک جمعیت کو ساتھ لے کر
بنو نضیر کے خلاف میدان میں نکل آئے.یہ وہ روایت ہے جس کی اکثر مورخین نے اتباع کی ہے.حتیٰ کہ یہی روایت تاریخ میں عام طور پر
شائع اور متعارف ہوگئی ہے، لیکن اس کے مقابل پر امام زہری کی یہ روایت صحیح احادیث میں مروی ہوئی
ہے کہ جنگ بدر کے بعد مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خاص طور پر کس سال اور کس ماہ میں مکہ کے رؤساء نے
بنو نضیر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو ورنہ ہم تمہارے
خلاف جنگ کریں گے.اس پر بنو نضیر نے باہم مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ کسی حکمت عملی کے ساتھ آنحضرت
(صلی اللہ علیہ وسلم ) کو قتل کر دیا جاوے اور اس کے لئے انہوں نے یہ تجویز کی کہ آپ کو کسی بہانہ سے
اپنے پاس بلائیں اور وہاں موقع پا کر آپ کو قتل کر دیں.چنانچہ انہوں نے آپ کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ
کے ساتھ اپنے علماء کا مذہبی تبادلہ خیالات کروانا چاہتے ہیں.کے اگر ہم پر آپ کی صداقت ظاہر ہوگئی
تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے.پس آپ مہربانی کر کے اپنے کوئی سے تمہیں اصحاب کو ساتھ لے کر تشریف
ل : ابن ہشام و ابن سعد
: ابن سعد وابن ہشام
۳ : وہ یہ خوب سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت دینے کے لئے سب سے زیادہ آسان اور پختہ ذریعہ مذہبی
تبلیغ کا بہانہ ہوسکتا ہے.
Page 605
۵۹۰
لے آئیں.ہماری طرف سے بھی تمہیں علماء ہوں گے اور پھر باہم تبادلہ خیالات ہو جائے گا.ایک طرف
تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا اور دوسری طرف یہ تجویز پختہ کر کے اس کے
مطابق پوری پوری تیاری بھی کر لی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہی یہودی علماء
جن کے پاس خنجریں پوشیدہ ہوں موقع پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں مگر قبیلہ بنو نضیر کی
ایک عورت نے ایک انصاری شخص کو جو رشتہ میں اس کا بھائی لگتا تھا اپنے قبیلہ والوں کے اس بدارا دے
سے بر وقت اطلاع دے دی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی گھر سے نکلے ہی تھے یہ اطلاع پاکر
واپس تشریف لے آئے ہے اور فوراً تیاری کا حکم دیا اور صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر بنونضیر کے
قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے اور جاتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا اور پھر ان کے رؤساء کو پیغام بھیجا کہ جو
حالات ظاہر ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں تمہیں مدینہ میں نہیں رہنے دے سکتا جب تک کہ تم
از سرنو میرے ساتھ معاہدہ کر کے مجھے یقین نہ دلاؤ کہ آئندہ تم بدعہدی اور غداری نہیں کرو گے مگر یہود
نے معاہدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اس طرح جنگ کی ابتدا ہوگئی اور بنونضیر نہایت متمردانہ
طریق پر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے.دوسرے دن آپ کو یہ اطلاع ملی یا آپ نے قرآئن سے خود معلوم کر لیا
کہ یہود کا دوسرا قبیلہ بنو قریظہ بھی کچھ بگڑا بیٹھا ہے.چنانچہ آپ صحابہ کے ایک دستہ کو ساتھ لے کر بنو
قریظہ کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا.بنوقریظہ نے جب دیکھا کہ راز کھل گیا
ہے تو وہ ڈر گئے اور معافی کے خواستگار ہو کر از سر نو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن وامان
اور باہمی اعانت کا معاہدہ کر لیا.جس پر آپ نے ان کا محاصرہ اٹھا لیا اور پھر بنونضیر کے قلعوں کی طرف
تشریف لے آئے ،لیکن بنونضیر بدستور اپنی ضد اور عداوت پر اڑے رہے اور ایک باقاعدہ جنگ کی
صورت پیدا ہوگئی..سیہ وہ دو مختلف روایتیں ہیں جو غزوہ بنو نضیر کے باعث کے متعلق بیان کی گئی ہیں اور گو تاریخی لحاظ سے
مؤخر الذکر روایت زیادہ درست اور صحیح ہے اور دوسری احادیث میں بھی زیادہ تر اسی روایت کی تائید پائی
جاتی ہے لیکن چونکہ پہلی روایت کو مؤرخین نے زیادہ کثرت کے ساتھ قبول کیا ہے اور بعض صحیح احادیث
میں بھی اس کی صحت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے.چنانچہ امام بخاری نے باوجود زہری کے قول کو ترجیح
: ابوداؤ د کتاب الخراج باب خبر النفير
ابوداؤ د کتاب الخراج باب خبر النفير
ابن مردویہ بحوالہ زرقانی حالات بنو نضیر
Page 606
۵۹۱
دینے کے قبیلہ عامر کے دو مقتولوں کی دیت کا بھی ذکر کیا ہے یا اس لئے ہماری رائے میں اگر دونوں
روایتوں
کو صحیح سمجھ کر ملا لیا جاوے تو کوئی حرج لازم نہیں آتا.البتہ اس سے غزوہ کے زمانہ کے متعلق ان
روایتوں میں سے کسی ایک روایت کو ترجیح دینی پڑے گی کیونکہ زمانہ کے لحاظ سے ہر دوروایات کو صحیح تسلیم
نہیں کیا جاسکتا.ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنونضیر کی طرف سے مختلف مواقع پر مختلف اسباب جنگ کے پیدا
ہوتے رہے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھیل دیتے رہے اور درگزر سے کام فرمایا لیکن جب
آخری سبب بئر معونہ کے واقعہ کے بعد ہوا ، تو آپ نے انہیں ان کی ساری کارروائیاں جتلا کر ان کے خلاف
فوج کشی فرمائی.گویا یہ جتنے مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ درست تھے مگر آخری
تحریکی سبب وہ تھا جو بنو عامر کے دو مقتولوں کی دیت کے مطالبہ کے وقت پیش آیا.واللہ اعلم بالصواب.یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ کعب بن اشرف جس کے قتل کا ذکر اوپر گزر چکا ہے اور جس نے مسلمانوں کے خلاف
گویا ایک آگ بھڑ کا رکھی تھی وہ بھی بنو نضیر سے تعلق رکھتا تھا.بہر حال یہود کے قبیلہ بنو نضیر نے خلاف عہدی اور غداری کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا
منصو بہ باندھا اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ ان حالات میں تمہارا مدینہ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے تم یہاں سے
چلے جاؤ تو انہوں نے تمرد اور سرکشی سے کام لیا اور تجدید معاہدہ سے انکار کر کے جنگ کے لئے تیار
ہو گئے.اس لئے مجبوراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے خلاف میدان میں نکلنا پڑا.چنانچہ آپ
نے اپنے پیچھے مدینہ کی آبادی میں ابن مکتوم کو امام صلوۃ مقرر فرمایا اور خود صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ
مدینہ سے نکل کر بنو نضیر کی بستی کا محاصرہ کر لیا اور بنو نضیر اس زمانہ کے طریق جنگ کے مطابق قلعہ بند
ہو گئے.غالباً اسی موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول اور دوسرے منافقین مدینہ نے بنونضیر کے رؤساء کو یہ کہلا
بھیجا کہ تم مسلمانوں سے ہرگز نہ دبنا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہاری طرف سے لڑیں گے.لیکن جب
عملاً جنگ شروع ہوئی تو بنو نضیر کی توقعات کے خلاف ان منافقین کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ کھلم کھلا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان میں آئیں ہے اور نہ بنو قریظہ کو یہ ہمت پڑی کہ مسلمانوں کے خلاف
میدان میں آکر بنو نضیر کی بر ملا مد دکریں.گو دل میں وہ ان کے ساتھ تھے اور درپردہ ان کی امداد بھی کرتے
تھے جس کا مسلمانوں کو علم ہو گیا تھا.بہر حال بنو نضیر کھلے میدان میں مسلمانوں کے مقابل پر نہیں نکلے
بخاری حالات غزوہ بنو نضیر
بخاری حدیث بنی التغير ومسلم باب اخراج الیہود
ابن ہشام
Page 607
۵۹۲
اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے لیکن چونکہ ان کے قلعے اس زمانہ کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے اس لئے ان کو
اطمینان تھا کہ مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اور آخر کار خود تنگ آکر محاصرہ چھوڑ جائیں گے اور اس
میں شک نہیں کہ اس زمانہ کے حالات کے ماتحت ایسے قلعوں کا فتح کرنا واقعی ایک بہت مشکل
اور پر از مشقت کام تھا اور ایک بڑا طویل محاصرہ چاہتا تھا.چنانچہ کئی دن تک مسلمان برابر محاصرہ کئے رہے
لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا.جب محاصرہ پر چند دن گزر گئے اور کوئی نتیجہ نہ نکلا اور بنونضیر بدستور مقابلہ پر ڈٹے
رہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ بنو نضیر کے ان کھجوروں کے درختوں میں سے جو
قلعوں کے باہر تھے بعض درخت کاٹ دئے جائیں.یہ درخت جو کاٹے گئے لینہ قسم کی کھجور کے درخت
تھے.ے جو ایک ادنی قسم کی کھجور تھی جس کا پھل عموماً انسانوں کے کھانے کے کام نہیں آتا تھا.اور اس حکم
میں منشا یہ تھا کہ تا ان درختوں کو کتا دیکھ کر بنو نضیر مرعوب ہو جائیں.اور اپنے قلعوں کے دروازے کھول
دیں اور اس طرح چند درختوں کے نقصان سے بہت سی انسانی جانوں کا نقصان اور ملک کا فتنہ وفسا درک
جائے.چنانچہ یہ تدبیر کارگر ہوئی اور ابھی صرف چھ درخت ہی کاٹے گئے تھے کہ بنو نضیر نے غالباً یہ خیال
کر کے کہ شاید مسلمان ان کے سارے درخت ہی جن میں پھل دار درخت بھی شامل تھے ، کاٹ ڈالیں گے
آه و پکار شروع کر دی حالانکہ جیسا کہ قرآن شریف میں تشریح کی گئی ہے صرف بعض درخت اور وہ بھی لینہ
قسم کے درخت کاٹنے کی اجازت تھی اور باقی درختوں کے محفوظ رکھنے کا حکم تھا اور ویسے بھی عام حالات
میں مسلمانوں کو دشمن کے پھل دار درخت کاٹنے کی اجازت نہیں تھی نے بہر حال یہ تدبیر کارگر ہوئی اور بنو نضیر
نے مرعوب ہوکر پندرہ دن کے محاصرہ کے بعد اس شرط پر قلعہ کے دروازے کھول دئے کہ ہمیں یہاں سے
اپنا ساز وسامان لے کر امن وامان کے ساتھ جانے دیا جاوے یہ وہی شرط تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
خود پہلے پیش کر چکے تھے اور چونکہ آپ کی نیت محض قیام امن تھی آپ نے مسلمانوں کی اس تکلیف اور
ان اخراجات کو نظر انداز کرتے ہوئے جو اس مہم میں ان کو برداشت کرنے پڑے تھے اب بھی بنو نضیر
کی اس شرط کو مان لیا اور محمد بن مسلمہ صحابی کو مقررفرمایا کہ وہ اپنی نگرانی میں بنونضیر کو امن وامان کے ساتھ
ابن ہشام وابن سعد
الروض الانف شرح سیرۃ ابن ہشام
۵: قرآن شریف سورۃ حشر ۶۰
کے ابن ہشام وابن سعد
: قرآن شریف سورۃ حشر ۶
زرقانی
موطا امام مالک کتاب الجہاد
Page 608
۵۹۳
مدینہ سے روانہ کردیں یا چنانچہ بنو نضیر بڑے ٹھاٹھ اور شان و شوکت سے اپنا سارا ساز و سامان حتی که خود
اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو مسمار کر کے ان کے دروازے اور چوکھٹیں اور لکڑی تک اکھیڑ کر اپنے ساتھ
لے گئے.اور لکھا ہے کہ یہ لوگ مدینہ سے اس جشن اور دھوم دھام کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے نکلے کہ
جیسے ایک برات نکلتی ہے.البتہ ان کا سامان حرب اور جائیداد غیر منقولہ یعنی باغات وغیرہ مسلمانوں کے
ہاتھ آئے اور چونکہ یہ مال بغیر کسی عملی جنگ کے ملا تھا اس لئے شریعت اسلامی کی رو سے اس کی تقسیم کا
اختیار خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اور آپ نے یہ اموال زیادہ تر ان غریب مہاجرین
میں تقسیم فرما دے ہے جن کے گزارہ جات کا بوجھ ابھی تک اس ابتدائی سلسلہ مواخات کے ماتحت انصار کی
جائیدادوں پر تھا اور اس طرح بالواسطہ انصار بھی اس مال غنیمت کے حصہ دار بن گئے.ھے
جب بنو نضیر محمد بن مسلمہ صحابی کی نگرانی میں مدینہ سے کوچ کر رہے تھے تو بعض انصار نے ان لوگوں
کو ان کے ساتھ جانے سے روکنا چاہا جو در حقیقت انصار کی اولاد سے تھے مگر انصار کی منت ماننے کے نتیجے
میں یہودی ہو چکے تھے اور بنو نضیر ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن چونکہ انصار کا یہ مطالبہ اسلامی
حم لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " (یعنی دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہ ہونا چاہئے ) کے خلاف تھا ، اس لئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاف اور یہود کے حق میں فیصلہ کیا اور فرمایا کہ جو شخص بھی
یہودی ہے اور جانا چاہتا ہے ہم اسے نہیں روک سکتے.البتہ بنو نضیر میں سے دو آدمی خود اپنی خوشی.مسلمان ہو کر مدینہ میں ٹھہر گئے.2
ایک روایت آتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کے متعلق یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شام
کی طرف چلے جائیں.یعنی عرب میں نہ ٹھہریں، لیکن باوجود اس کے ان کے بعض سر دار مثلاً سلام بن
ابی الحقیق اور کنانہ بن ربیع اور حیی بن اخطب وغیرہ اور ایک حصہ عوام کا بھی حجاز کے شمال میں
یہودیوں کی مشہور بستی خیبر میں جا کر مقیم ہو گیا اور خیبر والوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی ہے اور
جیسا کہ آگے چل کر اپنے موقع پر بیان ہوگا یہ لوگ بالآخر مسلمانوں کے خلاف خطرناک فتنہ انگیزی
اور اشتعال جنگ کا باعث بنے.بنو قریظہ جنہوں نے اس جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
زرین بحوالہ تلخيص الصحاح جلد اسورة حشر
ابن سعد
طبری
قرآن شریف سورة بقره : ۲۵۷
ابن ہشام
طبری
: ابوداؤ د باب خبر الحفير ه: ابن ہشام
: ابوداؤ د کتاب الجہاد
Page 609
۵۹۴
غداری کر کے اور اپنے عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر بنونضیر کی اعانت کی تھی ان پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا اور معاف فرما دیا.مگر ان بدبختوں نے اس احسان کا جو بدلہ دیا اس کا
ذکر آگے آتا ہے.غزوہ بنونضیر کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ حشر میں بیان ہوا ہے جوقریباً ساری کی ساری سورۃ اسی
غزوہ کے متعلق ہے.حضرت اُم المؤمنین زینب بنت خزیمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی
تھے جن کا نام عبد اللہ بن جحش تھا.وہ جنگ اُحد میں شہید
ہو گئے اور ان کی بیوی زینب بنت خزیمہ بیوگی کی حالت میں بے سہارا رہ گئیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو صلہ رحمی میں ایک بے نظیر نمونہ رکھتے تھے خود اپنی طرف سے زینب بنت خزیمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا
اور ان کی طرف سے رضا مندی کا اظہار ہونے پر ان کو اپنے عقد میں لے لیا.اس وقت زینب بنت خزیمہ
کی عمر کم و بیش تمہیں سال کی تھی مگر ان کی شادی پر ابھی صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ربیع الآخرم ہجری
میں وہ انتقال کر گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت البقیع میں دفن فرمایا.زینب بنت خزیمہ
ایک بہت نیک اور پارسا بی بی تھیں اور اپنے صدقہ و خیرات اور غرباء پروری کی وجہ سے عام طور پر
ام المساکین کے نام سے مشہور تھیں.ولادت حسین شعبان ۴ ہجری اسی سال ماہ شعبان میں حضرت فاطمہ کے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہوا
جس کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا ،حسین بھی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح عزیز تھے جیسا کہ ان کے بھائی حسن تھے.چنانچہ بعض اوقات آپ
محبت میں ان دونوں کو اپنے دو پھول کہہ کر یاد فرمایا کرتے تھے.کے یہ وہی امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو
یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے زمانہ میں ۶۱ ہجری کے ماہ محرم کی دسویں تاریخ کو ایک مظلوم حالت میں
شہید ہو کر اپنے محبوب حقیقی سے جاملے.اور جن کی شہادت کی یاد میں شیعہ لوگ آج تک ماتم کرتے اور
تعزیئے نکالتے ہیں.بخاری حدیث بنی النفير ومسلم باب اجلاء الیهود
زرقانی جلد ۳ حالات زینب بنت خزیمہ نیز اصابہ فی معرفتہ الصحابه
سے بخاری باب فضائل
: اصابه
Page 610
۵۹۵
غزوہ بدرالموعد ذ وقعده ۴ ہجری جنگ اُحد کے حالات میں یہ ذکر گزر چکا ہے کہ میدان سے
لوٹتے ہوئے ابوسفیان نے مسلمانوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ
سال بدر کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کرنے
کا اعلان فرمایا تھا.اس لئے دوسرے سال یعنی ۴ھ ہجری میں جب شوال کے مہینہ کا آخر آیا تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ ہزار صحابہ کی جمعیت کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے اور آپ نے اپنے پیچھے
عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی کو امیر مقرر فرمایا ہے
دوسری طرف ابوسفیان بن حرب بھی دو ہزار قریش کے لشکر کے ساتھ مکہ سے نکلا مگر باوجود اُحد کی فتح
اور اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ ہونے کے اس کا دل خائف تھا اور اسلام کی تباہی کے در پے ہونے کے
باوجود وہ چاہتا تھا کہ جب تک بہت زیادہ جمعیت کا انتظام نہ ہو جاوے وہ مسلمانوں کے سامنے نہ
ہو.چنانچہ ابھی وہ مکہ میں ہی تھا کہ اس نے ایک شخص نعیم نامی کو جو ایک غیر جانبدار قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا
مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر اور جھوٹ سچ
باتیں بتا کر جنگ سے نکلنے کے لئے باز رکھے.چنانچہ یہ شخص مدینہ میں آیا اور قریش کی تیاری اور
طاقت اور ان کے جوش وخروش کے جھوٹے قصے سنا سنا کر اس نے مدینہ میں ایک بے چینی کی حالت پیدا
کردی.حتی کہ بعض کمزور طبیعت لوگ اس غزوہ میں شامل ہونے سے خائف ہونے لگے لیکن جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی تحریک فرمائی اور آپ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم نے کفار کے
چیلنج کو قبول کر کے اس موقع پر نکلنے کا وعدہ کیا ہے، اس لئے ہم اس سے مختلف نہیں کر سکتے اور خواہ مجھے
اکیلا جانا پڑے میں جاؤں گا اور دشمن کے مقابل پرا کیلا سینہ سپر ہوں گا، تو لوگوں کا خوف جاتا رہا اور وہ
بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئے.بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ ہزار صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور دوسری
طرف ابوسفیان اپنے دو ہزار سپاہیوں کے ہمراہ مکہ سے نکلا لیکن خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ مسلمان تو
بدر میں اپنے وعدہ پر پہنچ گئے ،مگر قریش کا لشکر تھوڑی دور آ کر پھر مکہ کو واپس لوٹ گیا.اور اس کا قصہ یوں
ہوا کہ جب ابوسفیان کو نعیم کی ناکامی کا علم ہوا تو وہ دل میں خائف ہوا اور اپنے لشکر کو یہ تلقین کرتا ہوا
راستہ سے لوٹا کر واپس لے گیا کہ اس سال قحط بہت ہے اور لوگوں کو تنگی ہے اس لئے اس وقت لڑنا ٹھیک
ابن ہشام
: ابن سعد
Page 611
۵۹۶
نہیں ہے.جب کشائش ہوگی تو زیادہ تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کریں گے.اسلامی لشکر آٹھ دن تک بدر میں ٹھہرا اور چونکہ وہاں ماہ ذوقعدہ کے شروع میں ہر سال میلہ لگا کرتا
تھا.ان ایام میں بہت سے صحابیوں نے اس میلہ میں تجارت کر کے کافی نفع کمایا.حتی کہ انہوں نے اس
آٹھ روزہ تجارت میں اپنے رأس المال کو دو گنا کر لیا.جب میلے کا اختتام ہو گیا اور لشکر قریش نہ آیا
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے کوچ کر کے مدینہ میں واپس تشریف لے آئے اور قریش نے مکہ میں
واپس پہنچ کر مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں.یہ غزوہ غزوہ بدرالموعد کہلاتا ہے.تزوج ام سلمہ شوال ۴ ہجری اسی سال ماہ شوال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے
شادی فرمائی.ام سلمہ قریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی
تھیں اور اس سے پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد کے عقد میں تھیں جو ایک نہایت مخلص اور پرانے صحابی تھے
اور اسی سال فوت ہوئے تھے.جب اُم سلمہ کی عدت ( یعنی وہ میعاد جو اسلامی شریعت کی رو سے ایک بیوہ
یا مطلقہ عورت پر گزرنی ضرور ہوتی ہے پیشتر اس کے کہ وہ نکاح ثانی کرے ) گزرگئی تو چونکہ اُم سلمہ ایک
نہایت سمجھ دار با سلیقہ اور قابل خاتون تھیں اس لئے حضرت ابو بکر کو ان کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش
پیدا ہوئی ہے مگر ام سلمہ نے انکار کیا.آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے لئے ان کا خیال آیا جس کی
ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ام سلمہ کی ذاتی خوبیوں کے علاوہ جن کی وجہ سے وہ ایک شارع نبی کی بیوی بننے کی اہل
تھیں وہ ایک بہت بڑے پائے کے قدیم صحابی کی بیوہ تھیں اور پھر صاحب اولا د بھی تھیں جس کی وجہ سے
ان کا کوئی خاص انتظام ہونا ضروری تھا.علاوہ ازیں چونکہ ابوسلمہ بن عبدالاسد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے رضاعی بھائی بھی تھے.اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو اپنی طرف سے شادی کا
پیغام بھیجا.پہلے تو ام سلمہ نے اپنی بعض معذوریوں کی وجہ سے کچھ تامل کیا اور یہ عذر بھی پیش کیا کہ میری
عمراب بہت زیادہ ہوگئی ہے اور میں اولاد کے قابل نہیں رہی.لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی غرض اور تھی اس لئے بالآخر وہ رضا مند ہو گئیں اور ان کی طرف سے ان کے لڑکے نے ماں کا ولی ہوکر
ابن ہشام وابن سعد
طبری و زرقانی جلد ۳ حالات ام سلمه
۵ بخاری کتاب النکاح باب وان تجمعوابين الاختين
نسائی بحوالہ اصابه وزرقانی جلد۳ وا بن سعد حالات ام سلمه
: ابن سعد
نسائی کتاب النکاح باب النکاح الا بن امه
Page 612
۵۹۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی کر دی.جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے ام سلمہ ایک خاص
پائے کی خاتون تھیں اور نہایت فہیم اور ذ کی ہونے کے علاوہ اخلاص وایمان میں بھی ایک اعلیٰ مرتبہ رکھتی
تھیں اور ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابتداء حبشہ کی طرف
ہجرت
کی تھی.مدینہ کی ہجرت میں بھی وہ سب مستورات سے اول نمبر پر تھیں یا حضرت ام سلمہ پڑھنا بھی
جانتی تھیں یا اور مسلمان مستورات کی تعلیم و تربیت میں انہوں نے خاصہ حصہ لیا.چنا نچہ کتب حدیث
میں بہت سی روایات اور احادیث ان سے مروی ہیں اور اس جہت سے ان کا درجہ ازواج النبی میں دوسرے
نمبر پر اور کل صحابہ ( مردوزن ) میں بارہویں نمبر پر ہے.حضرت ام سلمہ نے بہت لمبی عمر پائی اور یزید بن
معاویہ کے زمانہ میں ۸۴ سال کی عمر میں فوت ہوئیں." اور وہ امہات المؤمنین میں سب سے آخری
فوت ہونے والی تھیں.چونکہ حضرت اُم سلمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سب سے بڑی
عمر کی تھیں حتی کہ وہ شادی کے وقت اولاد پیدا کرنے کے بھی ناقابل ہو چکی تھیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جو دورہ آپ اپنی بیویوں کے گھروں میں دریافت خیریت کے لئے روزانہ عصر کی
نماز کے بعد فرمایا کرتے تھے اس میں سب سے پہلے آپ حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے جاتے اور
سب سے آخر میں حضرت عائشہ کے گھر میں جاتے تھے جو عمر میں سب سے چھوٹی تھیں اور پھر اس کے بعد
جس بیوی کی باری ہوتی تھی اس کے گھر تشریف لے جاتے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب خاص اور عبرانی کی تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خط وکتابت کا سلسلہ
اب وسیع ہور ہا تھا اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ آپ کا کوئی مخلص صحابی عبرانی سے بھی واقفیت
پیدا کرے تا کہ یہود کے ساتھ خط و کتابت اور معاہدات وغیرہ کی تکمیل میں آسانی ہو اور دھو کے وغیرہ
کا احتمال نہ رہے چنانچہ اس غرض سے آپ نے اپنے ایک نوجوان صحابی زید بن ثابت انصاری سے جنہوں
نے جنگ بدر کے قیدیوں سے عربی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اور جو گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب خاص
یا پرائیوٹ سیکرٹری کا کام کرتے تھے ، ارشاد فرمایا کہ وہ عبرانی کا لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیں.چنانچہ زید
نے جو خاص طور پر ذہین واقع ہوئے تھے صرف پندرہ دن کی محنت سے عبرانی سیکھ لی..یہ امر بھی قابل ذکر
زرقانی واصابه
: بلاذری باب امر الحظ
ابن سعد جلد ۸ و تہذیب التہذیب
: : زرقانی واصا به حالات ام سلمه ۵ زرقانی جلد ۳ حالات حضرت ام سلمہ : اصابه ونمی
Page 613
۵۹۸
ہے کہ یہ وہی زید بن ثابت ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر کے زمانہ میں ان کے حکم کے ماتحت قرآن شریف
کو ایک مصحف یعنی کتاب کی صورت میں جمع کر کے لکھاے
جمع قرآن ہم نے جو او پر یہ لکھا ہے کہ زید بن ثابت انصاری نے حضرت
ابو بکر کے زمانہ خلافت میں
قرآن کریم کو مصحف کی صورت میں جمع کر کے لکھا تھا.اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے
پہلے قرآن مجید جمع نہیں تھا بلکہ حق یہ ہے کہ قرآن کریم جوں جوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا
جاتا تھا، آپ اسے الہی تفہیم کے ماتحت ترتیب دے کر نہ صرف خودا سے یاد کرتے جاتے تھے بلکہ بہت
سے دوسرے صحابہ کو بھی یاد کرا دیتے تھے اور جو صحابہ اس معاملہ میں زیادہ ماہر تھے ان کا آپ نے یہ فرض
مقرر کیا تھا کہ وہ دوسروں کو سکھائیں.اور مزید احتیاط کے طور پر آپ اسے ساتھ ساتھ لکھواتے بھی جاتے
تھے.چنانچہ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہی زید بن ثابت جنہوں نے بعد میں قرآن شریف کو ایک جلد کی
صورت میں اکٹھا کر کے لکھا اور جو ایک غیر معمولی طور پر ذہین آدمی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ
میں قرآنی وحی کے قلمبند کرنے پر مامور تھے یے اور ان کے علاوہ بعض اور اصحاب بھی اس خدمت کو سرانجام
دیتے تھے.مثلاً حضرت ابو بکر، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان ، حضرت علی ، زبیر بن العوام، شرجیل بن حسنہ،
عبد الله بن سعد بن ابی سرح ، ابی بن کعب ، عبد اللہ بن رواحہ وغیرہ.غرض قرآن مجید کے جمع و ترتیب
کا حقیقی کام سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کی ہدایت کے ماتحت ہو گیا تھا اور یہ
صرف ایک قیاس ہی نہیں ہے بلکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر آتا ہے.چنا نچہ عبداللہ بن عباس سے
بخاری باب جمع القرآن
یہ یا درکھنا چاہئے کہ قرآن شریف کا نزول قریبا تئیس سال یا
زیادہ صحیح طور پر ساڑھے بائیس سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ ہوا تھا.اورگو در میان میں بعض ناغے ہو جاتے تھے
اور بعض ایام میں زیادہ حصہ اکٹھا نازل ہو جاتا تھا، لیکن اگر حسابی طور پر قرآن شریف کی مجموعی آیات کو جو قریباً چھ ہزار دو
سو چونتیس ( ۶۲۳۴ ) ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے دنوں پر جو قمری حساب سے قریباًسات
ہزار نوسوستر (۷۹۷۰) بنتے ہیں پھیلا کر دیکھا جاوے تو فی یوم صرف ۷۸ ۰ یعنی ایک آیت سے بھی کم کا حساب نکلتا ہے
اور یہی اس قرآنی آیت کی عملی تفسیر ہے کہ رَثَلْته ترتیلا ( سورۃ فرقان :۳۳) یعنی ہم نے قرآن کو یکلخت نہیں
اتا را بلکہ بہت آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتارا ہے.بخاری فضائل القرآن
ه فتح الباری جلد ۹ صفحه ۱۹، زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۶
بخاری کتاب فضائل القرآن باب کتاب البینی
Page 614
۵۹۹
روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ثالث فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
طریق تھا کہ جب آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ آپنے کا تب وحی کو بلوا کر اسے وہ وحی لکھوا دیتے
تھے اور ساتھ ہی یہ فرما دیتے تھے کہ اسے فلاں سورۃ میں فلاں موقع پر رکھو.اسی طرح آپ خود ہی سورتوں
کی ترتیب بھی مقرر فرما دیتے تھے.اور یہ طریق آپ کا ابتداء دعویٰ نبوت سے تھا.چنانچہ کتاب کے حصہ
اول میں ہم لکھ چکے ہیں کہ جب مکہ کے ابتدائی سالوں میں حضرت عمرؓ مسلمان ہوئے تو انہیں اسلام کی
تحریک قرآن کی تلاوت سے ہی ہوئی تھی جو خباب بن الارت ایک لکھے ہوئے صحیفہ سے حضرت عمر کی بہن
اور بہنوئی کو پڑھ کر سنا رہے تھے.الغرض قرآن شریف شروع سے ہی ساتھ ساتھ ضبط تحریر میں آکر مرتب
ہوتا اور جمع ہوتا گیا تھا.اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ اپنی نمازوں میں قرآن شریف کی
با قاعدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات نمازوں میں لمبی لمبی قرآتیں پڑھتے تھے.چنانچہ ایک
روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایک ہی تہجد یعنی نصف شب کی نماز میں قرآن شریف کی پہلی
پانچ سورتوں کی جو مجموعی طور پر قرآن کریم کے پنجم حصہ کے برابر بنتی ہیں اکٹھی اور بالترتیب قرآت فرمائی
تھی.اور یہی وہ لمبے قیام ہیں جن کی وجہ سے بسا اوقات آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے.اور بعض
روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ہر سال ماہ رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف
کا دور فرمایا کرتے تھے اور آخری سال دو دفعہ مکمل دور فرمایا یہ سب باتیں اس بات
کو یقینی طور پر ظاہر کرتی
ہیں کہ قرآن شریف کی ترتیب اور جمع کا حقیقی کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا.پس زید بن ثابت کے جمع کرنے سے صرف یہ مراد ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر خلیفہ اول کے حکم
اور ان کی نگرانی کے ماتحت قرآن مجید کو ایک مصحف یعنی جلد یا کتاب کی صورت میں اکٹھا کر کے لکھا تا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کردہ قرآن کی ایک مستند اور یکجائی کاپی ضبط میں آجاوے اور
روایت سے پتہ لگتا ہے کہ پھر اسی مصحف سے بعد میں حضرت عثمان خلیفہ ثالث نے متعد د مصدقہ
نقلیں تیار کرا کے انہیں اس وقت کی اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں میں بھجوا دیا اور پھر انہی مصدقہ نقول
ابوداؤ دوترمذی و مسند احمد بحوالہ مشکوة فضائل القرآن و فتح الباری جلد ۹ صفحه ۲۰،۱۹ و صفحه ۳۹
: ابن ہشام جلد اصفحه ۲۰،۱۱۹ اوز رقانی جلد اصفحه ۲۷۴،۲۷۳
: ابوداؤ د کتاب الصلوۃ باب ما يقول الرجل في ركوعه
بخاری کتاب فضائل قرآن باب كان جبريل يعرض القرآن
بخاری ابواب التهجد
Page 615
۶۰۰
سے آگے مزید اشاعت ہوتی گئی لیے علاوہ ازیں ہر زمانہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں حفاظ نے قرآن کریم
کو اپنے سینوں میں لفظ بلفظ محفوظ کر کے اس کی حفاظت کا ایک مزید ظاہری سبب مہیا کیا.اس بات کا
اندازہ کرنے کے لئے کہ مسلمانوں کو قرآن شریف کے حفظ کرنے کا کس قدر شوق رہا ہے صرف یہ روایت
کافی ہے کہ جب ایک دفعہ کسی غرض سے حضرت عمرؓ کو قرآن کے حفاظ کے پتہ لینے کی ضرورت پیش آئی تو
معلوم ہوا کہ اس وقت کی اسلامی افواج کے صرف ایک دستہ میں تین سو سے زائد حافظ قرآن تھے.کہے
موجودہ زمانہ میں بھی جبکہ لوگوں میں دین کا شوق بہت کم ہو گیا ہے اسلامی دنیا میں حفاظ قرآن کی تعداد
یقین لا کھوں سے کم نہیں ہوگی.ترتیب قرآن یہ سوال کہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب کسی اصول پر قائم ہے یا نہیں ؟ اور اگر ہے تو
کس پر ؟ تاریخ سے تعلق نہیں رکھتا اور نہ ہی ایک تاریخی تصنیف میں اس قسم کے سوال
کا تشریحی جواب دیا جاسکتا ہے مگر اس جگہ اس کے متعلق ایک مختصر سا اشارہ کر دینا غالبا بے سود نہ
ہوگا.سو جاننا چاہئے کہ جیسا کہ دوست و دشمن میں مسلّم ہے اور تاریخ وحدیث اس کے حوالوں سے بھری
پڑی ہیں کہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب اس کے نزول کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے بلکہ وہ ایک
جدا گانہ ترتیب ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدائی تفہیم کے مطابق مقرر فرمائی تھی.چنانچہ
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَہ کے یعنی ” قرآن کا جمع کرنا خود ہمارے ذمہ ہے
اور ہم ہی اس کام کو سر انجام دیں گے.اور ظاہر ہے کہ جمع قرآن کا کام خصوصاً جبکہ اسے نزول کی ترتیب
سے ہٹا کر دوسری ترتیب میں جمع کیا گیا ہو ترتیب کے ساتھ لازم و ملزوم کے طور پر ہے اور جیسا کہ اوپر
بیان کیا گیا ہے حدیث میں تو صراحت کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے
نزول پر اور ہر سورۃ کے مکمل ہونے پر خود ہدایت فرماتے تھے کہ اس آیت یا سورۃ کو فلاں جگہ رکھو."
اندریں حالات خواہ کسی شخص کو موجودہ قرآنی ترتیب سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس بات میں
کوئی شبہ نہیں کیا
جاسکتا کہ قرآن میں کوئی نہ کوئی اصول ترتیب ضرور مقصود ہے.دراصل غور کیا جاوے تواصل نزول کی
ترتیب کو چھوڑ نا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نئی ترتیب میں کوئی نہ کوئی اصول ضرور مد نظر رکھا گیا ہے.ورنہ
بخاری کتاب فضائل قرآن باب جمع القرآن و فتح الباری جلد ۹ صفحه ۱۸،۱۷
کنز العمال باب في القرآن فضل في فضائل القرآن
ابوداؤ د واحمد بحوالہ فتح الباری جلد ۹ صفحه ۲۰،۱۹ صفحه ۳۹
سورۃ قیامة: ۱۸
Page 616
۶۰۱
کوئی وجہ نہیں تھی کہ نزول کی ترتیب کو ترک کر کے کوئی اور ترتیب اختیار کی جاتی.مثلاً ایک ہال میں چند آدمی
یکے بعد دیگرے داخل ہوتے ہیں.اب اگر ہال کا منتظم ان آدمیوں کے متعلق خاص اہتمام کے ساتھ یہ انتظام
کرتا ہے کہ وہ داخل ہونے کی ترتیب سے نہ بیٹھیں بلکہ انہیں کسی اور ترتیب کے ساتھ بٹھا تا ہے تو اس کا یہی
فعل اس بات کی دلیل ہو گا کہ خواہ اس کا اصول ترتیب کسی کو معلوم ہو یا نہ ہومگر اس کے مدنظر کوئی نہ کوئی
اصول ضرور ہے.ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ داخلہ کی ترتیب کو تبدیل کیا جا تا.کیونکہ کوئی ہوش وحواس
رکھنے والا انسان یونہی لغو طور پر بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا.اس موقع پر اکثر یورپین محققین یہ کہا کرتے ہیں کہ ہال کے منتظم نے داخلہ کی ترتیب کو بدل کر
سائزنگ کے اصول پر لوگوں کو بٹھا دیا ہے.یعنی قرآنی سورتوں کو ان کی لمبائی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا
ہے.مگر یہ ایک سراسر بے بنیاد اور غلط خیال ہے.کیونکہ اول تو ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ جمع و ترتیب
کا کام خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی تفہیم کے ماتحت سرانجام دیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم جیسے انسان کی طرف اس قسم کا عبث فعل کبھی بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا.ایسا فعل وہی شخص کر سکتا
ہے جو عقل وخرد سے بالکل عاری ہو.نزول کی ترتیب جس سے کم از کم بعض تاریخی فوائد کے حصول میں
آسانی ہو سکتی تھی اسے محض اس وجہ سے ترک کرنا کہ قرآنی سورتیں لمبے اور چھوٹے ہونے کے لحاظ سے
ترتیب دی جاسکیں جس میں کوئی بھی علمی فائدہ متصور نہیں ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم تو در کنار ایک معمولی عقل کا آدمی بھی اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات تو اس سے بہت بالا وارفع ہے.دوسرے سورتوں کا وجود ہی جس کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہے
کسی ترتیب کا نتیجہ ہے کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن شریف سورتوں کی صورت میں نازل نہیں
ہوا بلکہ آیات کی صورت میں بہت آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے اور سورتیں آیات کے جمع ہونے سے
عالم وجود میں آئی ہیں.علاوہ ازیں یہ بات عملاً بھی بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ قرآن میں سورتوں
کے لمبا چھوٹا ہونے کی ترتیب مد نظر رکھی گئی ہے اور قرآنی سورتوں کی آیات کی تعداد کا ایک سرسری
مطالعہ بھی اس کی تردید کے لئے کافی ہے کیونکہ بیسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ بعض لمبی سورتیں ہیں جو پیچھے
رکھی گئی ہیں اور بعض چھوٹی سورتیں ہیں جو پہلے آگئی ہیں اور نہ معلوم مغربی محققین اس معاملہ میں اس قدر
کوتاہ نظری اور فاش غلطی کے مرتکب کس طرح ہوئے ہیں.الغرض اس بات میں ہر گز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اوّل قرآن شریف کی موجودہ ترتیب اس
Page 617
۶۰۲
کے نزول کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے.دوم نہ ہی یہ ترتیب سورتوں کے طول وقصر کے لحاظ سے ہے بلکہ
سوم یہ کوئی اور ہی ترتیب ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدائی ارشاد کے ماتحت مقرر فرمائی
تھی.اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترتیب کیا ہے؟ اس کے جواب میں اس جگہ صرف اس قدر اشارہ کیا
جا سکتا ہے کہ قرآن شریف جو خدا کا قول ہے اس میں اسی قسم کا اصول ترتیب مدنظر رکھا گیا ہے جو خدا
کے فعل یعنی صحیفہ قدرت میں پایا جاتا ہے یعنی جس طرح اس جسمانی عالم میں دنیا کی مادی زندگی اور
ترقی و بہبودی کے سامان و ذرائع مہیا کئے جا کر اس میں ایک ترتیب رکھی گئی ہے اسی طرح کی خدا کے قول
یعنی قرآن شریف میں ایک ترتیب ہے جو علم النفس کے ان ابدی اصول کے ماتحت قائم کی گئی ہے جو دنیا کی
اخلاقی اور تمدنی اور روحانی زندگی اور اصلاح و ترقی کے لئے بہترین اثر رکھتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ جس
طرح بعض لوگوں کو اس عالم جسمانی میں کوئی ترتیب نظر نہیں آتی اسی طرح روحانی بینائی سے محروم لوگوں کو
قرآنی ترتیب بھی نظر نہیں آتی.مگر جو لوگ گہرے مطالعہ کے عادی ہیں اور روحانی کلام کی حقیقت کو سمجھنے
کے لئے اپنے اندر ضروری بینائی اور تقدس و طہارت رکھتے ہیں وہ اس ترتیب کو علی قدر مراتب سمجھتے اور اس
کے اثر کو اپنے نفوس میں محسوس کرتے ہیں.اس جگہ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اگر موجودہ ترتیب ہی اصلاح وتربیت اور روحانی تاثیر کے لحاظ سے
بہترین تھی تو پھر اسی کے مطابق قرآن کا نزول کیوں نہ ہوا تا کہ صحابہ کی جماعت بھی جو قرآنی تعلیم کی سب
سے پہلی حامل بنتی تھی ان اثرات سے متمتع ہوتی.تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کے حالات اور بعد میں
آنے والے مسلمانوں کے حالات میں اختلاف ہے.صحابہ کے لئے وہی ترتیب بہترین تھی جس کے
مطابق قرآن شریف نازل ہوا.مگر جب ایک ابتدائی جماعت قائم ہوگئی تو پھر آئندہ کے لئے مستقل
طور پر وہ ترتیب بہترین تھی جو موجودہ قرآن میں پائی جاتی ہے اور یہ اختلاف دواصول کے ماتحت ہے.اول تو بوجہ اس کے کہ صحابہ کی جماعت وہ پہلی جماعت تھی جو اسلامی شریعت کے مطابق قائم ہوئی
اور اس سے پہلے کوئی جماعت اسلامی شریعت کی حامل نہیں تھی اور نہ ہی دنیا میں اسلامی شریعت کا وجود
تھا.اور قرآن کے ذریعہ سے پہلے طریق و تمدن کو مٹاکر ایک بالکل ہی نئے طریق و تمدن کی بنیاد پڑنی
تھی، اس لئے ضروری تھا کہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے ان کی ذہنیت اور ماحول کے مناسب حال
قرآنی احکامات کا نزول ہوتا تا کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے اور نئی تعلیم کو اپنے اندر جذب
کرنے میں آسانی پاتے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے بہترین صورت یہ تھی کہ سب سے پہلے اس قسم کی
Page 618
۶۰۳
آیات کا نزول ہوتا جن میں صرف عقیدہ کی درستی مدنظر ہے اور مشرکانہ خیالات کو مٹا کر تو حید کو قائم کیا گیا
ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلامی طریق عبادات اور اسلامی طریق معاملات اور اسلامی طریق تمدن
اور اسلامی طریق سیاست کے متعلق اوامر ونواہی نازل ہوتے.چنانچہ ایسا ہی کیا گیا.لیکن جب ایک
جماعت اسلامی شریعت کی حامل تیار ہوگئی اور آئندہ پھیلاؤ اور ترقی کے لئے ایک وجود بطور تخم کے یعنی ایک
نیوکلیئس (NUCLEUS تیار ہو گیا تو اب اس تخم یا نیوکلیکس کی آئندہ ترقی کے لئے وہ ابتدائی ترتیب
نزول غیر طبعی اور ناموزوں تھی.اس لئے اسے بدل کر وہ ترتیب دے دی گئی جو اس کے لئے مناسب تھی.چنانچہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب بالکل اس اصول کے ماتحت ہے جو ایک تیار شدہ جماعت کے استحکام
اس کے پھیلاؤ اور ترقی کے لئے موزوں ترین ہے.دوسرا اصول نزول کی ترتیب کو بدل کر دوسری ترتیب کے اختیار کرنے میں یہ مد نظر تھا کہ نزول کی
ترتیب زیادہ تر ان حالات کے مطابق چلتی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پیش آتے
تھے.مثلاً چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ابھی کفار پر اتمام حجت ہو رہا تھا اور مسلمانوں کو
صبر وشکیب کے سانچے میں ڈھال کر نکالنا مقصود تھا.اس لئے مکی آیات میں جہاد کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ
صبر و برداشت کی تعلیم پر زور ہے.لیکن جب اتمام حجت ہو چکا اور صحابہ بھی صبر و برداشت کے سانچے میں
ڈھل چکے اور کفار کے مظالم سے مسلمانوں کو اپنا وطن تک چھوڑنا پڑا اور ظالم کی سزا کا وقت آگیا تو اس وقت
جہاد کی آیات نازل ہوئیں اسی طرح مکہ میں چونکہ مسلمانوں کی کوئی جماعت بصورت جمعیت نہیں تھی اور کفار
کے مظالم نے انہیں بالکل منتشر کر رکھا تھا.یعنی ان کی کوئی اجتماعی زندگی نہیں تھی اس لئے مکہ میں اسلامی
طریق تمدن و معاملات کے متعلق آیات نازل نہیں ہوئیں.لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کو ایک اجتماعی
زندگی نصیب ہوئی تو اس کے مناسب حال آیات کا نزول ہوا اگر اس نزول میں حالات کی مناسبت اور
مطابقت کو محوظ نہ رکھا جاتا تو یقینا ابتدائی مسلمانوں کے لئے نئی شریعت کو اپنے اندر جذب کرنا اور اس پر صحیح طور پر
عامل ہونا سخت مشکل ہو جاتا.لہذا قرآن کے نزول کوحتی الوسع حالات پیش آمدہ کے ساتھ ساتھ چلایا گیا تھا تا کہ
اس کی تعلیم صحابہ میں جذب ہوتی جاوے لیکن جب سب نزول ہو چکا اور ایک جماعت قرآنی شریعت کی
حامل وجود میں آگئی تو پھر اس ترتیب کو قائم رکھنا ضروری نہ تھا بلکہ پھر اس بات کی ضرورت تھی کہ آئندہ کی
مستقل ضروریات کے مطابق اسے ترتیب دی جاوے.چنانچہ ایسا ہی کیا گیا.بخاری کتاب فضائل القرآن باب تالیف القرآن و فتح الباری جلد ۹ صفحه ۳۷
Page 619
۶۰۴
اگر اس جگہ کسی کو یہ اعتراض پیدا ہو کہ نزول کی ترتیب بدلنے سے قرآن کی تاریخی حیثیت ضائع ہوگئی
ہے تو یہ ایک بودا اور فضول اعتراض ہوگا کیونکہ اول تو جب حدیث و تاریخ میں قرآنی آیات کی نزول کی
ترتیب بیشتر طور پر محفوظ ہے اور ذرا سی محنت اور توجہ کے ساتھ اس بات کا پتہ لگ سکتا ہے کہ کوئی آیت
یا سورۃ کب نازل ہوئی تھی تو اس صورت میں ہرگز یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن کی تاریخی حیثیت ضائع ہوگئی
ہے بلکہ حق یہ ہے کہ وہ پوری طرح محفوظ ہے اور دوست و دشمن نے اسے تسلیم کیا ہے صرف فرق یہ پیدا ہوا
ہے کہ اگر قرآن کو اس کے نزول کے مطابق ترتیب دیا جاتا تو اس کی تاریخی حیثیت بدیہی اور عیاں ہوتی
اور اب وہ محنت اور توجہ کے ساتھ نکالنی پڑتی ہے.دوسرے یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ قرآن شریف کی اصل غرض وغایت تاریخ کی حفاظت نہیں ہے
بلکہ اس قانون کا بہترین صورت میں مہیا کرنا ہے جو لوگوں کی تمدنی اور اخلاقی اور روحانی ترقی کے لئے
ضروری ہے اور جو بندہ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے.پس اس کی ترتیب میں بھی انہی اصول کا مد نظر رکھا جانا
ضروری تھا جوان اغراض کو بہترین صورت میں پورا کر سکتے تھے اور اگر اس کی ترتیب میں ان اصولوں
کو قربان کر کے تاریخی پہلو کوترجیح دی جاتی تو یہ ایک نہایت غیر حکیمانہ فعل ہوتا.اس مضمون کو ختم کرنے سے پہلے یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب بھی
اس رنگ کی ترتیب نہیں ہے جس میں عام کتب کی طرح بابوں اور فصلوں اور پیروں وغیرہ میں مضمون
کو تقسیم کیا گیا ہو کیونکہ اس قسم کی ترتیب قرآن کی غرض وغایت کے منافی تھی.قرآن کا دعوی ہے کہ وہ
سب اقوام اور سب زمانوں کے لئے ایک شریعت لایا ہے اور اس میں علوم کے خزانے مخفی ہیں جو بقدر
ضرورت ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے.اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی تحقیق سے علماء کبھی سیر نہیں
ہوں گے اور نہ اس کے عجائب کبھی ختم ہوں گے.اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قرآنی آیات
کے صرف ظاہری معانی پر ہی حصر نہیں ہے بلکہ اس کی ہر آیت کے نیچے متعد د بطون ہیں اور ہر بطن آگے
متعد دشاخیں رکھتا ہے.بالفاظ دیگر اسلام قرآن شریف کو ایک روحانی عالم کے طور پر پیش کرتا ہے ٹھیک
اسی طرح جس طرح یہ دنیا ایک جسمانی عالم ہے.پس اس کی ترتیب کے اصول کو سمجھنے کے لئے بھی
ا سورۃ اعراف:۱۵۹،سورۃ فرقان : ۲ ، سورۃ سبا: ۲۹
ترمذی ابواب القرآن جلد ۲ صفحه ۱۴۹
: سورۃ حجر : ۲۲ ، سورۃ بنی اسرائیل:۹۰
: شرح السنہ بحوالہ مشکوة کتاب العلم فصل ثانی وطبرانی کبیر بحوالہ جامع الصغیر سیوطی جلد اصفحہ ۹۱
Page 620
بہترین مثال اس دنیا کی ہوسکتی ہے جس طرح اور جس رنگ میں اس دنیا میں ترتیب پائی جاتی ہے کہ ہر چیز
با وجود ایک دوسرے سے بظاہر جدا اور لاتعلق نظر آنے کے دراصل اپنی گہرائیوں میں ایک دوسرے سے
پیوست اور مربوط ہے اور ایک مخفی زنجیر بلکہ مختلف جہات سے کئی مخفی زنجیریں اس کے مختلف حصوں کو ایک
دوسرے سے منسلک کئے ہوئے ہیں اسی طرح قرآن کی گہرائیوں میں ربط و اتحاد کی کڑیاں چلتی ہیں
اور ٹھیک جس طرح اس جسمانی عالم میں محققین اور سائنس دان اپنی اپنی اہلیت اور اپنی اپنی تحقیق کے
مطابق علوم کے جواہر نکالتے رہتے ہیں اسی طرح قرآن کے روحانی عالم کے سمندر میں غوطہ لگانے والوں
کے لئے بھی کسی زمانہ میں روحانی موتیوں کی کمی نہیں رہی اور نہ آئندہ ہوگی.اور یہ بات قرآن کریم کے
سب سے بڑے معجزوں میں سے بڑا معجزہ ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کی ترتیب کو ایسے طور پر رکھا گیا ہے
کہ وہ با وجود حجم میں ساری آسمانی کتابوں میں سے چھوٹا ہونے کے اپنے اندر روحانی علوم کا ایک نہ ختم
ہونے والا خزانہ رکھتا ہے جو حسب تحقیق محققین اور حسب ضرورت زمانہ ہمیشہ ظاہر ہوتے رہے ہیں اور
ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے یا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ترتیب کو عام کتب کی طرح معین مضمون کے ٹکڑوں
میں تقسیم کر کے بابوں اور فصلوں اور پیروں وغیرہ کی صورت میں نہیں رکھا گیا کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو اس
کے معانی کی ساری وسعت کھوئی جاتی اور اس کا مفہوم ایک محدود اور معین صورت اختیار کر کے اپنی
ظاہری اور بد یہی صورت میں بالکل مقید ہو جاتا.خلاصہ کلام یہ کہ قرآن شریف اس بات کا مدعی ہے
کہ اس کے اندر علوم کے بے انتہا خزانے مخفی ہیں جو ہمیشہ بقدر ضرورت ظاہر ہوتے رہیں گے اور اس
کی تحقیق کا میدان
کبھی ختم نہیں ہوگا اور قرآن کی یہ حیثیت اور اس کے نزول کی یہ غرض یقیناً فوت
ہو جاتی اگر اس کی ترتیب کو عام کتب کی طرح بابوں اور فصلوں وغیرہ میں مضمون وار تقسیم کر کے ایک
ٹھوس صورت میں جکڑ دیا جاتا.پس جہاں یہ یا درکھنا چاہئے کہ قرآن ایک نہایت مرتب اور منظم کتاب
ہے اور یہ بالکل غلط ہے کہ اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے وہاں یہ بات بھی کبھی نہیں بھولنی چاہئے کہ اس
کی ترتیب عام کتب کی طرح نہیں ہے بلکہ اس جسمانی عالم کے اصول پر ہے جس میں معانی کی بے شمار
گہرائیاں مخفی ہیں اور ان گہرائیوں میں ربط و اتحاد کی لا تعداد زنجیر میں ایک جال کے طور پر پھیلی ہوئی
ہیں جن سے ہر شخص اور ہر زمانہ اپنی کوشش اور اپنی استعداد اور اپنی ضرورت اور اپنے حالات کے
مطابق فائدہ اٹھاتا اور اٹھا سکتا ہے.ہمارا یہ مختصر نوٹ اس جگہ بے شک ایک دعویٰ سے زیادہ حیثیت
ا ازالہ اوہام صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۷
Page 621
۶۰۶
نہیں رکھتا مگر افسوس ہے کہ اس تاریخی تصنیف میں اس وسیع اور علمی مضمون کے لئے اس مختصر اشارے
سے زیادہ کی گنجائش نہیں ورنہ اس دعوی کے ثبوت میں دلائل کا ایک سورج چڑھایا جا سکتا ہے.اب
ہم اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس بین الاقوام معاہدہ نے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوا تھا
بین الاقوام قاضی کی حیثیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح مدینہ کی مختلف اقوام
میں ایک پولیٹکل لیڈر اور انتظامی حاکم کی حیثیت دے دی تھی
اور آپ اس بین الاقوام جمہوری سلطنت کے گویا صدر قرار پائے تھے جو مدینہ میں ہجرت کے بعد قائم ہوئی
تھی.اس پوزیشن میں اہم مقدمات بھی آپ ہی کے سامنے پیش ہونے لگ گئے تھے اور آپ ہر قوم کے
ضابطہ عدالت کے ماتحت ان کا فیصلہ فرماتے تھے.چنانچہ روایت آتی ہے کہ ۴ ہجری کے آخر میں آپ کے
سامنے ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کا ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ان کے خلاف زنا کا الزام ثابت
کیا گیا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی علماء سے پوچھا کہ اس بارہ میں موسوی شریعت کیا فتویٰ
دیتی ہے.انہوں نے دھو کے اور افترا کے طریق پر یہ جواب دیا کہ جو شخص زنا کرے اسے ہمارے ہاں
منہ کالا کر کے اور سواری پر الٹا سوار کر کے پھرایا جاتا ہے.اس وقت عبد اللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم
تھے اور اب مسلمان ہو چکے تھے پاس ہی بیٹھے تھے.انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! یہ لوگ غلط کہتے ہیں.تورات میں زنا کی سزا سنگسار کرنا لکھی ہے.چنانچہ تو رات منگوائی گئی اور گو یہودیوں نے بہت پردہ ڈالنے
کی کوشش کی حتی کہ بہانے بہانے سے اس آیت پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپانا بھی چاہامگر عبداللہ بن سلام
نے یہ صاف طور پر دکھا دیا کہ از روئے تو رات زنا کی سزار حجم ہے اور ان کو شرمندہ ہونا پڑا اور چونکہ یہ
معاہدہ تھا کہ ہر قوم کے مقدمات اس کے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کئے جائیں گے اور اسلام میں تو
ابھی تک زنا وغیرہ کی حدود کے متعلق احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے اس لئے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ
یہودی شریعت کے مطابق ان دونوں کو سنگسار کر دیا جاوے.چنانچہ وہ دونوں مرد و عورت سنگسار کر دئے
گئے.یہ ۴ ہجری کے آخر کا واقعہ ہے.حضرت علی کی والدہ کی وفات اسی سال ۴ ہجری کے آخر میں حضرت علیؓ کی عمر رسیدہ والدہ نے
جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا مدینہ میں انتقال کیا.یہ بزرگ خاتون
بخاری کتاب المحاربین و تاریخ الخمیس حالات ۴ ھ
Page 622
۶۰۷
گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قائم مقام تھیں کیونکہ آپ کے دادا عبدالمطلب کی وفات کے بعد
انہوں نے ہی آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اور ویسے بھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے بہت محبت رکھتی تھیں.اس لئے ان کی وفات کا آپ کو بہت صدمہ ہوا اور ان کی نعش کو دیکھ کر آپ کی
آنکھیں پُر آب ہو گئیں.وفور محبت میں آپ نے اپنی قمیض اتار کر انہیں پہنائی اور خود ان کی قبر میں اترے
اورسب
تکنین وتدفین کا انتظام خود کیا.اور جب وہ قبر میں اتاری گئیں تو آپ نے رقت بھری آواز میں
فرمایا جَزَاكِ اللَّهُ مِنْ أُمِّ خَيْرًا لَقَدْ كُنْتِ خَيْرَامٍ ، خدا تعالیٰ تمہیں میری طرف سے میری ایک
بہت اچھی ماں بننے کی بہترین جزا دے تم حقیقتا ایک نہایت ہی اچھی ماں
تھیں.کتاب کے حصہ اول
میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ فاطمہ بنت اسد اور ابوطالب کی نرینہ اولا دچار لڑکوں یعنی طالب ، عقیل، جعفر اور
حضرت علی پر مشتمل تھی اور ایک لڑکی تھی جس کا نام ام ہانی تھا.غزوہ دومۃ الجندل اور اسلامی جنگوں اب تک جو جنگی کارروائیاں کی گئیں تھیں وہ بالواسطہ
یا بلا واسطه محض دفاع کے طور پر تھیں.اسی دفاع کا حصہ میں ایک نیا اضافہ ربیع الاول ۵ ہجری
وہ ہمیں تھیں جو بعض قبائل عرب کے ساتھ امن وامان
کے معاہدے کرنے کے لئے اختیار کی گئیں.نیز اس وقت تک جو سفر اختیار کئے گئے تھے وہ سب مرکزی
حجاز اور نجد کے علاقہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن اب یہ میدان وسیع ہونے لگا.چنانچہ دومتہ الجندل جس کے
غزوہ کا ہم اس وقت ذکر کرنے لگے ہیں.وہ شام کی سرحد کے قریب واقع تھا اور مدینہ سے اس کا فاصلہ
پندرہ سولہ دن کی مسافت سے کم نہ تھا.اس غزوہ کی وجہ یہ ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ دومۃ الجندل میں
بہت سے لوگ جمع ہو کر لوٹ مار کر رہے ہیں اور جو مسافر یا قافلہ وغیرہ وہاں سے گزرتا ہے اس پر حملہ کر کے
اسے تنگ کرتے اور اس کا مال و متاع لوٹ لیتے ہیں.اور ساتھ ہی یہ اندیشہ بھی پیدا ہوا کہ کہیں یہ لوگ
مدینہ کا رخ کر کے مسلمانوں کے لئے موجب پریشانی نہ ہوں.چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی
کارروائیوں کی ایک اہم غرض قیام امن بھی تھی اس لئے باوجود اس کے کہ ان لوگوں کی اس لوٹ مار سے
مدینہ کے مسلمانوں کو حقیقتاً کوئی زیادہ اندیشہ نہیں تھا.آپ نے صحابہ میں تحریک فرمائی کہ اس ڈاکہ زنی
اور ظلم کے سلسلہ کو روکنے کے لئے وہاں چلنا چاہئے چنانچہ آپ کی تحریک پر ایک ہزار صحابی اس
ل : تاریخ الخمیس جلد اصفحه ۵۲۶ : ابن سعد و معجم البلدان
: ابن سعد
Page 623
۶۰۸
دور دراز کے تکلیف دہ سفر کو اختیار کر کے آپ کے ساتھ ہو لئے.اور آپ ہجرت کے پانچویں سال ماہ
ربیع الاول میں مدینہ سے روانہ ہوئے یے اور پندرہ سولہ دن کی طویل اور پر از مشقت مسافت طے کرنے
کے بعد دومۃ الجندل کے قریب پہنچے.مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں کی خبر پا کر ادھر ادھر منتشر
ہو گئے تھے اور گو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چند دن تک ٹھہرے اور آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھی
ادھر ادھر روانہ فرمائے تا کہ ان مفسدین کا کچھ پتہ چلے مگر وہ کچھ ایسے لا پتہ ہوئے کہ ان کو کوئی سراغ نہ ملا.البتہ ان کا ایک چرواہا مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہو گیا
اور آپ چند دن قیام کے بعد مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے..جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے یہ غزوہ اس رنگ میں پہلا غزوہ تھا کہ اس کی غرض یا کم از کم بڑی
غرض ملک میں امن کا قیام تھی.اہل دومہ کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑانہیں تھا وہ مدینہ سے اتنی دور
تھے کہ ان کی طرف سے بظاہر یہ اندیشہ کسی حقیقی خطرہ کا موجب نہیں ہوسکتا تھا کہ وہ اتنے لمبے سفر کی
صعوبت برداشت کر کے مدینہ میں مسلمانوں کی پریشانی کا موجب ہوں گے.پس ان کے مقابلہ کے لئے
پندرہ سولہ دن کا تکلیف دہ سفر اختیار کرنا حقیقتا سوائے اس کے اور کسی غرض سے نہیں تھا کہ انہوں نے جو
اپنے علاقہ میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا اور بے گناہ قافلوں اور مسافروں کو تنگ کرتے تھے اس کا
سد باب کیا جاوے.پس مسلمانوں
کا یہ سفر محض رفاہ عام اور ملک کی مجموعی بہبودی کے لئے تھا جس میں ان
کی اپنی کوئی غرض مد نظر نہیں تھی.اور یہ ایک عملی جواب ہے ، ان لوگوں کا جنہوں نے سراسر ظلم اور بے انصافی
کے ساتھ مسلمانوں کی ابتدائی جنگی کارروائیوں کو جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے
ما تحت اختیار کیں جارحانہ یا خود غرضانہ قرار دیا ہے.اس غزوہ کا ایک نتیجہ تو یہ ہوا کہ اہل دومہ مرعوب ہو کر اپنی ان مفسدانہ کارروائیوں سے باز آگئے
اور مظلوم مسافروں کو اس ظلم سے نجات مل گئی اور دوسرے شام کی سرحد میں جہاں ابھی تک مسلمانوں کا
صرف نام ہی پہنچا تھا اور لوگ اسلام کی حقیقت سے بالکل نا آشنا تھے اسلام کا ایک گونہ انٹروڈکشن ہو گیا
اور اس علاقہ کے لوگ مسلمانوں کے طریق و تمدن سے ایک حد تک واقف ہو گئے.دومۃ الجندل کے قرب وجوار میں بعض عیسائی بھی آباد تھے.مگر روایات میں یہ مذکور نہیں ہے کہ
ا: ابن سعد
معجم البلدان
ابن ہشام
: ابن سعد
Page 624
آیا یہ مفسدین جن کے خلاف یہ مہم اختیار کی گئی عیسائی تھے یا کہ بت پرست مشرک.مگر حالات سے
قیاس ہوتا ہے کہ غالباً یہ لوگ مشرک ہوں گے کیونکہ اگر یہ مہم عیسائیوں کے خلاف ہوتی تو مؤرخین ضرور
اس کا ذکر کرتے.واللہ اعلم
،،
ابھی آپ واپس نہیں پہنچے تھے کہ آپ کے پیچھے مدینہ میں سعد بن عبادۃ رئیس قبیلہ خزرج کی ماں کا
انتقال ہو گیا.جب آپ واپس آئے تو آپ نے ان کی قبر پر جا کر دعا فرمائی اور جب سعد نے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ ! میری ماں اچانک بیہوشی کی حالت میں فوت ہوگئی ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر انہیں بولنے
کا موقع ملتا تو وہ ضرور کچھ صدقہ و خیرات کرتیں.کیا اس صورت میں اب ان کی طرف سے میں صدقہ
کر سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا ”ہاں! بے شک ان کی طرف سے صدقہ کر دو.“ اور سعد کے دریافت
کرنے پر کہ کون سا صدقہ بہتر ہوگا آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے آرام کے لئے کوئی کنواں لگوا دو.چنانچہ
سعد نے ایک کنواں لگوا کر اسے رفاہ عام کے لئے وقف کر دیا.ایک دوسری روایت میں ہے کہ سعد کی
والدہ بیہوشی کی حالت میں تو فوت نہیں ہوئی تھیں مگر چونکہ سعد خود مدینہ سے غیر حاضر تھے اور تمام
جائیدا دسعد کی تھی اس لئے سعد کی والدہ با وجود خواہش کے صدقہ نہیں کرسکی تھیں.اس کے بعد جب
سعد واپس آئے تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی ماں کی طرف سے ایک باغیچہ
خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے
مدینہ میں خسوف قمر اور صلوٰۃ خسوف اسی سال ماہ جمادی الآخر میں مدینہ میں چاند کوگر ہن لگا ھے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ
نماز کے لئے جمع ہو جائیں.چنانچہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت تک نماز میں مصروف
رہے کہ چاند کھل گیا اور اس وقت سے اسلام میں چاند گرہن کی نماز با قاعدہ مشروع ہوگئی.جب ایک
طرف مسلمان نماز میں مصروف تھے تو دوسری طرف یہود یہ سمجھ کر اپنے برتن وغیرہ بجا رہے تھے کہ چاند کو
کسی نے جادو کر دیا ہے جو اس طرح شور کرنے سے جاتا رہے گا.اس موقع پر یہ ذکرنا مناسب نہ ہوگا کہ اسلام کی یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے نہ صرف
ابن سعد
: ابوداؤد کتاب الزكوة
: تاریخ خمیس
: مؤطا باب صدقة الحمى عن الميت
تاریخ الخمیس جلد اصفحه ۵۲۸ بروایت ابن حبان : تاریخ الخمیس جلد اصفحه ۵۲۸
Page 625
۶۱۰
بے جا تو ہمات کو مٹایا ہے بلکہ ہر ایسے موقع پر جہاں بیجا تو ہمات کا دروازہ کھل سکتا تھا ایسی عبادات مقرر
کر دی ہیں جو فوراً انسان کو خدا کی طرف متوجہ کر کے مشرکانہ خیالات کا سد باب کر دیتی ہیں.چنانچہ
خسوف وغیرہ کے موقع پر عبادت مقرر کرنے میں بڑی حکمت یہی ہے کہ تا مسلمانوں کو اس بات کی
طرف توجہ پیدا ہو کہ دنیا کی زندگی میں جو نو ر اور روشنی بھی انسان
کو پہنچتی ہے اس کا ظاہری آلہ خواہ
کوئی چیز ہومگر در اصل اس کا منبع ذات باری تعالی ہی ہے اور اس لئے اگر کسی وجہ سے اس روشنی میں کوئی
روک پیدا ہو جاوے تو خواہ یہ روک عام طبعی قوانین کے ماتحت ہی ہوا سے اس موقع پر خدا ہی کی طرف
رجوع کرنا چاہئے.دراصل اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر حرکت وسکون اور اس کے ماحول کے ہر تغیر
کے ساتھ ذکر الہی کو وابستہ کر دیا ہے تا کہ کوئی گھڑی اس پر غفلت کی نہ آئے.مگر یہ ایک الگ مذہبی مبحث
ہے جس میں پڑنا ایک مؤرخ کا کام نہیں.مکہ کا قحط اور قریش کے ساتھ غزوہ بدر الموعد کے بیان میں مکہ کے قحط کا بھی ذکر گزر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی چکا ہے یہ قحط ابھی تک جاری تھا.قریش مکہ اس قحط سے
بہت تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور غرباء کو تو سخت مصیبت
کا سامنا ہوا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس تکلیف کی اطلاع ہوئی تو آپ نے از راہ ہمدردی
مکہ کے غرباء کے لئے اپنی طرف سے کچھ چاندی بھجوائی یا اور اس طرح آپ نے اس بات کا ایک عملی
ثبوت دیا کہ آپ کا دل آپ کے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی ایک گہری اور حقیقی ہمدردی رکھتا ہے اور یہ
کہ آپ کی مخالفت صرف عقائد و خیالات کے ساتھ تھی نہ کہ کسی انسان کے ساتھ.بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور موقع پر بھی مکہ والے قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو ان کی طرف
سے ابوسفیان بن حرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
آیا تھا اور رشتہ داری اور قرابت کا واسطہ
دے کر تحریک کی تھی کہ ان کے لئے اس قحط کے دور ہونے کی دعا کی جاوے یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
اہل مکہ کے جذبات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مخلوط قسم کے تھے.یعنی وہ آپ کی ذاتی نیکی اور
تقوی وطہارت کے بھی قائل تھے مگر آپ کی تعلیم کو اپنے قدیم طریق عمل اور مشرکانہ خیالات کے خلاف
پاتے ہوئے اسے مٹانے کے بھی درپے تھے.خیالات میں اس قسم کا خلط علم النفس کے اصول کے ماتحت
ناممکن نہیں ہے.: تاریخ الخمیس جلد اصفحه ۵۲۸
بخاری ابواب الاستسقاء
Page 626
۶۱۱
زینب بنت جحش کی شادی ۵ ہجری اسی سال یعنی ہجرت کے پانچویں سال میں غزوہ بنی
مصطلق سے کچھ عرصہ پہلے جو شعبان ۵ ہجری میں واقع
ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے شادی فرمائی.بعض مؤرخین مثلاً ابن اثیر اور
صاحب خمیس وغیرہ نے زینب بنت جحش کی شادی کو غزوہ بنی مصطلق کے بعد رکھا ہے مگر یہ ان کی غلطی
ہے کیونکہ یہ بات صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ پر اتہام لگایا گیا تھا اس وقت
زینب بنت جحش کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت عائشہ کے خلاف الزام لگائے جانے کا واقعہ مسلمہ
طور پر غزوہ بنی مصطلق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.حضرت زینب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ
بنت عبدالمطلب کی صاحبزادی تھیں اور باوجود نہایت درجہ نیک اور متقی ہونے کے ان کی طبیعت میں اپنے
خاندان کی بڑائی کا احساس بھی کسی قدر پایا جاتا تھا.اس کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
طبیعت اس قسم کے خیالات سے بالکل پاک تھی اور گو آپ خاندانی حالات کو مدنی رنگ میں قابل لحاظ
سمجھتے تھے مگر آپ کے نزدیک بزرگی کا حقیقی معیار ذاتی خوبی اور ذاتی تقوی وطہارت پر مبنی تھا.جیسا کہ
قرآن شریف فرماتا ہے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ الْقُكُمْ یعنی ”اے لوگو! تم میں سے جو
شخص زیادہ متقی ہے وہی زیادہ بڑا اور صاحب عزت ہے.پس آپ نے بلاکسی تامل کے اپنی اس عزیزہ یعنی
زینب بنت جحش کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام اور متبنی زید بن حارثہ کے ساتھ تجویز فرما دی.پہلے تو زینب
نے اپنی خاندانی بڑائی کا خیال کرتے ہوئے اسے ناپسند کیا.لیکن آخر کار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
پر زور خواہش کو دیکھ کر رضا مند ہو گئیں.بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تجویز کے مطابق
زینب اور زید کی شادی ہوگئی.اور گوزینب نے ہر طرح شرافت سے نبھاؤ کیا.مگر زید نے اپنے طور پر یہ
محسوس کیا کہ زینب کے دل میں ابھی تک یہ خلش مخفی ہے کہ میں ایک معزز خاندان کی لڑکی اور آنحضرت
ملی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار ہوں اور زید ایک محض آزاد شدہ غلام ہے اور میرا کفو نہیں.دوسری طرف
خود زید کے دل میں بھی زینب کے مقابلہ میں اپنی پوزیشن کے چھوٹا ہونے کا احساس تھا.اور اس احساس
نے آہستہ آہستہ زیادہ مضبوط ہو کر ان کی خانگی زندگی کو بے لطف کر دیا اور میاں بیوی میں ناچاقی رہنے
لگی.جب یہ نا گوار حالت زیادہ ترقی کر گئی تو زید بن حارثہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
کتاب المغازی حدیث افک
: سورة حجرات : ۱۴
ابن جریر طبرانی بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۴۵ نیز ابن سعد جلد ۸ حالات زینب بنت جحش
Page 627
۶۱۲
ہوئے اور بزعم خود زینب کے سلوک کی شکایت کر کے انہیں طلاق دے دینے کی اجازت چاہی.اور
ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ انہوں نے یہ شکایت کی کہ زینب سخت زبانی سے کام لیتی ہے اس لئے میں
اسے طلاق دینا چاہتا ہوں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعا یہ حالات معلوم کر کے صدمہ ہوا مگر
آپ نے زید کو طلاق دینے سے منع فرمایا.اور غالبا یہ بات محسوس کر کے کہ زید کی طرف سے نبھاؤ کی کوشش
میں کمی ہے آپ نے انہیں نصیحت فرمائی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کر کے جس طرح بھی ہو بھاؤ کی کوشش
کروی چنانچہ قرآن شریف میں بھی آپ کے یہ الفاظ مذکور ہوئے ہیں کہ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللہ ہے یعنی اے زید ! اپنی بیوی کو طلاق نہ دو اور خدا کا تقویٰ اختیار کرو.“
آپ کی اس نصیحت کی وجہ یہ تھی کہ اول تو اصولاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کو نا پسند فرماتے
تھے.چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اَبغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.یعنی ساری حلال
چیزوں میں سے طلاق خدا کو زیادہ نا پسند ہے.اور اسی لئے اسلام میں صرف انتہائی علاج کے طور پر اس
کی اجازت دی گئی ہے.دوسرے جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے امام زین العابدین
علی بن حسین کی روایت ہے اور امام زہری نے اس روایت کو مضبوط قرار دیا ہے..چونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ وحی الہی ہو چکی تھی کہ زید بن حارثہ بالآخر زینب کو طلاق دے دیں
گے اور اس کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی اس لئے آپ اس معاملہ میں اپنا ذاتی تعلق سمجھتے
ہوئے بالکل غیر متعلق اور غیر جانب دارانہ رویہ رکھنا چاہتے تھے اور اپنی طرف سے اس بات کی پوری پوری
کوشش کرنا چاہتے تھے کہ زید اور زینب کے تعلق کے قطع ہونے میں آپ کا کوئی دخل نہ ہو اور جب تک نبھاؤ
کی صورت
ممکن ہو بھاؤ ہوتا رہے اور اسی خیال کے ماتحت آپ نے بڑے اصرار کے ساتھ زید کو یہ نصیحت
فرمائی کہ تم طلاق نہ دو اور خدا کا تقویٰ اختیار کر کے جس طرح بھی ہو سکے نبھاؤ کرو.آپ کو یہ بھی اندیشہ
تھا کہ اگر زید کی طلاق کے بعد زینب آپ کے عقد میں آئیں تو لوگوں میں اس کی وجہ سے اعتراض
ہوگا کہ آپ نے اپنے منتلیٹی کی مطلقہ سے شادی کر لی ہے اور خواہ نخواہ ابتلاء کی صورت پیدا ہوگی.چنانچہ
ل بخاری کتاب التوحید باب كان عرشه على الماء.بخاری کتاب التوحید و فتح الباری جلد ۸ و حاکم بروایت لباب النقول باب تفسیر سورۃ احزاب
: سورۃ احزاب : ۳۸
زرقانی جلد ۳ حالات زینب بنت جحش و فتح الباری جلد ۸ صفحه ۴۰۳
: فتح الباری جلد ۸ صفحه ۴۰۳
۵ : ابوداود کتاب الطلاق
Page 628
۶۱۳
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ اَنْ تَخْشُهُ
یعنی اے نبی ! تو اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھا وہ بات جسے خدا نے آخر ظاہر کرنا تھا اور تو لوگوں
کی وجہ سے ڈرتا تھا اور یقیناً خدا اس بات کا بہت زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈرا جاوے.“
بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو تقویٰ اللہ کی نصیحت کر کے طلاق دینے سے منع فرمایا
اور آپ کی اس نصیحت کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہوئے زید خاموش ہو کر واپس آگئے مگر ا کھڑی ہوئی
طبیعتوں کا ملنا مشکل تھا اور جو بات نہ بنی تھی نہ بنی اور کچھ عرصہ کے بعد زید نے طلاق دے دی.جب زینب کی عدت ختم ہو چکی تو ان کی شادی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی نازل ہوئی کہ
آپ
کو انہیں خود اپنے عقد میں لے لینا چاہئے.اور اس خدائی حکم میں علاوہ اس حکمت کے کہ اس سے
زینب کی دلداری ہو جائے گی اور مطلقہ عورت کے ساتھ شادی کرنا مسلمانوں میں عیب نہ سمجھا جائے گا یہ
حکمت مد نظر تھی کہ چونکہ زید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متمنی تھا اور آپ کا بیٹا کہلاتا تھا.اس لئے
جب آپ خود اس کی مطلقہ سے شادی فرمالیں گے تو اس بات کا مسلمانوں میں ایک عملی اثر ہوگا کہ منہ بولا
بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اور نہ اس پر حقیقی بیٹوں والے احکام جاری ہوتے ہیں اور آئندہ کے لئے عرب کی
جاہلانہ رسم مسلمانوں میں پورے طور پر مٹ جائے گی.چنانچہ اس بارہ میں قرآن شریف جو تاریخ اسلامی
کاسب سے زیادہ صحیح ریکارڈ ہے یوں فرماتا ہے.فَلَمَّا قَضَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرًا زَ وَجْنُكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَج
فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا O
یعنی جب زید نے زینب سے قطع تعلق کر لیا تو ہم نے زینب کی شادی تیرے ساتھ کر دی تاکہ
مومنوں کے لئے اپنے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ بیویوں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی روک نہ
رہے.بعد اس کے کہ وہ منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں سے قطع تعلق کر لیں اور خدا کا یہ حکم اسی طرح پورا
ہونا تھا.الغرض اس خدائی وحی کے نازل ہونے کے بعد جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش
سورۃ احزار
۳۸ :
: سورۃ احزاب : ۳۸
Page 629
۶۱۴
اور خیال کا قطعاً کوئی دخل نہیں تھا.آپ نے زینب کے ساتھ شادی کا فیصلہ فرمایا اور پھر زید کے ہاتھ ہی
زینب کو شادی کا پیغام بھیجا.اور زینب کی طرف سے رضا مندی کا اظہار ہونے پر ان کے بھائی ابواحمد بن
جحش نے ان کی طرف سے ولی ہو کر چار سو درہم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح
کر دیا ہے اور اس طرح وہ قدیم رسم جو عرب کی سرزمین میں راسخ ہو چکی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذاتی نمونہ کے نتیجہ میں اسلام میں بیخ و بن سے اکھیڑ کر پھینک دی گئی.اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ عام مؤرخین و محدثین کا یہ خیال ہے کہ چونکہ زینب کی شادی کے
متعلق خدائی وحی نازل ہوئی تھی اور خدا کے خاص حکم سے یہ شادی وقوع میں آئی اس لئے ظاہری طور پر ان
کے نکاح کی رسم ادا نہیں کی گئی.مگر یہ خیال درست نہیں ہے.بے شک خدا کے حکم سے یہ شادی ہوئی اور کہا
جا سکتا ہے کہ آسمان پر نکاح پڑھایا گیا مگر اس وجہ سے شریعت کی ظاہری رسم سے جو وہ بھی خدا ہی کی مقرر
کردہ ہے آزادی حاصل نہیں ہو سکتی.چنانچہ ابن ہشام کی روایت جس کا حوالہ اوپر درج کیا گیا ہے اور
جس میں ظاہری رسم نکاح کا واقع ہونا بتایا گیا ہے اس معاملہ میں واضح ہے اور کسی شک وشبہ کی گنجائش
نہیں رہنے دیتی.اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دوسری امہات المؤمنین کے مقابلہ میں زینب یہ فخر کیا
کرتی تھیں کہ ” تمہارے نکاح تمہارے ولیوں نے زمین پر پڑھائے ہیں اور میرا نکاح آسمان پر ہوا
ہے اس سے بھی یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ زینب کے نکاح کی ظاہری رسم ادا نہیں ہوئی.کیونکہ باوجود
ظاہری رسم کی ادائیگی کے ان کا یہ فخر قائم رہتا ہے کہ ان کا نکاح خدا کے خاص حکم سے آسمان پر ہوا مگر اس
کے مقابل پر دوسری امہات المؤمنین کی شادیاں عام اسباب کے ماتحت محض ظاہری رسم کی ادائیگی کے
ساتھ وقوع میں آئیں.ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذن کے زینب
کے پاس تشریف لے گئے تھے اور اس سے بھی یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ان کے نکاح کی ظاہری رسم ادا نہیں
ہوئی.مگر غور کیا جاوے تو اس بات کو بھی ظاہری رسم کے ادا ہونے یا نہ ہونے کے سوال سے کوئی تعلق نہیں
ہے کیونکہ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر بغیر اجازت چلے گئے تھے تو یہ
غلط اور خلاف واقعہ ہے کیونکہ بخاری کی صریح روایت میں یہ ذکر ہے کہ شادی کے بعد زینب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں نہ کہ آپ ان کے گھر گئے تھے.تے اور اگر اس روایت سے
مسلم کتاب النکاح باب زواج زینب بنت جحش
بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ احزاب
سیرۃ ابن ہشام جلد ۳ حالات ازواج
Page 630
۶۱۵
یہ مراد ہے کہ جب وہ رخصت ہو کر آپ کے گھر آگئیں تو اس کے بعد آپ ان کے پاس بغیر اذن کے تشریف
لے گئے تو یہ کوئی غیر معمولی اور خلاف دستور بات نہیں ہے.کیونکہ جب وہ آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر
آگئی تھیں تو پھر آپ نے بہر حال ان کے پاس جانا ہی تھا اور آپ کو اذن کی ضرورت نہیں تھی.پس اذن
نہ لینے والی روایت کا قطعاً کوئی تعلق اس سوال سے نہیں ہے کہ آپ کے اس نکاح کی ظاہری رسم ادا کی گئی یا
نہیں اور حق یہی ہے کہ جیسا کہ ابن ہشام کی روایت میں تصریح کی گئی ہے باوجود خدائی حکم کے اس نکاح
کی با قاعدہ رسم ادا کی گئی تھی اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ ایسا ہوا ہو کیونکہ اول تو عام قاعدہ میں استثنا کی کوئی
وجہ نہیں تھی اور دوسرے جبکہ اس نکاح میں ایک رسم کا توڑنا اور اس کے اثر کو زائل کرنا مقصود تھا تو اس بات
کی بدرجہ اولیٰ ضرورت تھی کہ یہ نکاح بڑے اعلان کے ساتھ علی رؤس الا شہاد وقوع میں آتا.پردے کے احکام کا نزول نکاح کے دوسرے یا تیسرے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
مکان میں صحابہ کی دعوت ولیمہ فرمائی اور چونکہ اس نکاح میں خاص
طور پر اعلان مقصود تھا اس لئے آپ نے اپنی ساری بیویوں میں حضرت زینب کا ولیمہ زیادہ بڑے پیمانے پر
کیا ہے اس وقت تک چونکہ پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے صحابہ بے تکلف آپ کے گھر کے اندر
ہی آگئے اور ان میں بعض لوگ کھانے سے فارغ ہو کر بھی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو کر وہیں بیٹھے
رہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی.مگر چونکہ آپ کی طبیعت میں حیا کا مادہ بہت
تھا آپ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے اور ان صحابہ کو باتوں کی مصروفیت میں خود خیال نہ رہا.نتیجہ یہ ہوا
کہ بہت دیر ہوگئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو گیا.آخر آپ خود اٹھ کھڑے
ہوئے اور آپ کو اٹھتے دیکھ کر اکثر صحابہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ سے رخصت ہو کر مکان
سے نکل گئے لیکن تین شخص پھر بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے.یہ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے.لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف
لائے تو ابھی تک یہ لوگ وہیں بیٹھے تھے اسی طرح آپ کو دو تین دفعہ آنا جانا پڑا اور آخر کار جب یہ لوگ آپ
کے مکان سے چلے گئے تو آپ واپس تشریف لے آئے.بعض اوقات الہی احکام کے نزول کے لئے بھی
محرکات پیدا ہو جاتے ہیں یعنی حکم نے تو بہر حال نازل ہونا ہوتا ہے مگر کوئی واقعہ اس کا وقتی محرک بن جاتا
ہے.چنانچہ یہی واقعہ پردے کے ابتدائی احکامات کے نزول کا تحریکی سبب بن گیا اور پردے کے متعلق وہ
جلد ۳ حالات ازواج النبی
بخاری کتاب النکاح باب الوليمة حق
Page 631
۶۱۶
ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر پردے کی پابندی
عائد کی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر محرم لوگوں کی آزادانہ آمد و رفت رک گئی ہے
اس کے بعد آہستہ آہستہ پردے کے متعلق مزید احکامات نازل ہوتے رہے حتی کہ بالآخر اس نے وہ صورت
اختیار کر لی جو اس وقت قرآن شریف و حدیث میں موجود ہے.یے اور جس کی رو سے مسلمان عورت کی جائز
اور ضروری آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے عورت کو غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے بدن اور لباس کی زینت
کے برملا اظہار سے منع فرمایا گیا ہے.نیز غیر محرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں اکیلے
ملاقات کرنا نا جائز قرار دے دیا گیا ہے اور اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو یہ وہ قیود ہیں جو ایک طرف
تو عورت کی صحت اور اس کی علمی ترقی اور قومی اور ملکی کاموں میں اس کے حصہ لینے اور دوسرے معاملات
میں اس کی جائز آزادی میں کوئی روک نہیں بنتیں اور دوسری طرف غیر محرم مرد و عورت کے بالکل آزادانہ
اور بے حجابانہ میل جول سے جو خلاف اخلاق اور مضرت رساں نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اور جو بے پر دملکوں
میں عموماً پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کا ان قیود سے سد باب ہو جاتا ہے.اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو صورت پردے کی مسلمانوں میں رائج ہے وہ
بالعموم صحیح اسلامی احکام کے مطابق نہیں ہے.کیونکہ اگر کہیں نا واجب سختی سے کام لے کر بیچاری عورت کو
اس کے گھر کی چار دیواری میں قریب قریباً ایک قیدی کی طرح بند رکھا جاتا ہے جس سے اس کی صحت اور
تعلیم و تربیت اور اس کا تمدن وغیرہ تباہ ہو رہے ہیں تو کہیں مغرب کی کورانہ تقلید میں اسے ناواجب آزادی
دے دی گئی ہے جس سے سوسائٹی کے اخلاق و عادات پر ضرر رساں اثر پڑ رہا ہے.اور یہ ہر دور ستے
افراط و تفریط کے رستے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا.اسلامی تعلیم کی رو سے عورت اپنی زینت کے
برملا اظہار سے رکتے ہوئے تمام قسم کی جائز تفریحات اور جائز کاموں میں حصہ لے سکتی ہے مگر اسے بالکل
کھلے منہ پھر نے اور غیر محرم مردوں کے ساتھ خلوت میں اکیلے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ
یہ طریق اپنے اندر فتنے کے احتمالات رکھتا ہے جس کا سد باب ضروری ہے.یورپ کے بعض ممالک میں
بھی جہاں پردے کی حدود کو بالکل توڑ دیا گیا ہے اعلیٰ طبقہ کے شرفاء کے گھروں میں اس قدر احتیاط ضرور
بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ احزاب
: قرآن شریف سورة نور : ۳۲ وسورة احزاب ۳۴ و بخاری تفسیر سورة نور وتفسير سورة احزاب و تفسير سورة ممتحنه
و كتاب النكاح
Page 632
۶۱۷
برتی جاتی ہے کہ عام طور پر جو ان لڑکیاں بغیر کسی محرم مرد یا معمر رفیق عورت کے بالکل آزادانہ طور پر
ادھر ادھر نہیں آتی جاتیں اور نہ غیر محرم مردوں کے ساتھ خلوت میں آزادانہ ملاقات کرتی ہیں اور جو
لڑکیاں اس معاملہ میں زیادہ آزادی دکھاتی ہیں انہیں عموماً شریف سوسائٹی میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی بالکل غیر مقید اور بے حجابانہ آزادی کو یورپ جیسی بے حجاب سرزمین
میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا اور یہی وہ اصول ہے جسے اسلام نے زیادہ جامعیت اور زیادہ خوبی کے ساتھ
اختیار کر کے اور اس کے ساتھ زینت کے چھپانے کے اصول کو شامل کر کے پردے کے احکام جاری کئے
ہیں اور اس معاملہ میں افراط و تفریط کے رستوں سے بچ کر ایک میانہ روی کا طریق قائم کر دیا ہے.دراصل اگر غور کیا جاوے تو پر دہ پر سارا اعتراض اس عملی طریق کی وجہ سے ہے جو آج کل بعض اسلامی
ممالک اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں میں رائج ہے اور جو زیادہ تر اسلامی سلطنتوں کی کمزوری کے
زمانہ میں سیاسی حالات کے ماتحت مجبوراً مسلمانوں کو اختیار کرنا پڑا تھا.مگر بعد میں ایک رسم کے طور پر ایک
مستقل اور زیادہ سخت صورت اختیار کر گیا.ورنہ اس معاملہ میں اصل اسلامی حکم جو قرآن وحدیث سے پتہ
لگتا ہے اور ابتدائی مسلمانوں کا اصل تعامل جو تاریخ و حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ ہرگز ایسا نہیں کہ اس پر
کوئی معقول اعتراض ہو سکے بلکہ ہر شخص جو ٹھنڈے طور پر غور کرنے کا عادی ہے اس کی خوبی کا قائل ہوئے
بغیر نہیں رہ سکتا.اسلامی پردہ کا لب لباب صرف یہ ہے کہ اول غیر محرم مرد وعورت ایک دوسرے کے
سامنے اپنی نظروں کو نیچار کھیں اور عورت اپنے چہرہ اور بدن اور لباس کی زینت کو کسی غیر محرم مرد پر نظر یا لمس
وغیرہ کے ذریعہ ظاہر نہ کرے یا دوم یہ کہ غیر محرم مرد و عورت کسی ایسی جگہ میں جو دوسروں کی نظر سے اوجھل
ہوخلوت میں اکیلے ملاقات نہ کریں.ان دو حد بندیوں کوملحوظ رکھتے ہوئے جن میں سراسر سوسائٹی کی
بہبودی اور اخلاق کی حفاظت مد نظر ہے ایک مسلمان عورت پردہ کے معاملہ میں ہر طرح آزاد ہے.وہ
درس گاہوں میں تعلیم حاصل کر سکتی اور تعلیم دے سکتی ہے.وہ ورزش اور سیر و تفریح کے لئے گھر سے باہر نکل
سکتی ہے.وہ خرید وفروخت کر سکتی ہے.وہ پبلک جلسوں وغیرہ میں شریک ہو سکتی ہے.وہ غیر محرم مردوں
سے ملاقات کر سکتی ہے اور ان کی بات سن سکتی اور ان کو اپنی بات سنا سکتی ہے.وہ محنت ومزدوری کر سکتی
ہے.وہ دفاتر اور محکموں اور شفا خانوں اور کارخانوں میں کام کر سکتی ہے.وہ قومی اور ملکی کاموں میں حصہ
لے قرآن شریف سورة نور : ۳۲ و بخاری تفسیر سورة ممتحنه
: بخاری کتاب النکاح باب لَا يَخُلُونَ رَجُلٌ وَبَابُ مَا يَجُوزُ اَنْ يَخْلُوَ
Page 633
۶۱۸
لے سکتی ہے.وہ جنگوں میں مناسب خدمت سرانجام دینے کے لئے شریک ہوسکتی ہے.غرض اسلامی پردہ
عورت کی تعلیم و تربیت، اس کی نشو و نما ، اس کے ضروری مشاغل ،اس کی جائز تفریحات میں ہرگز کوئی
روک نہیں ہے.اور تاریخ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں مسلمان
عورتیں تمام ان جائز کاموں میں حصہ لیتی تھیں جو اس زمانہ میں پیش آتے تھے.وہ تعلیم حاصل کرتی اور
تعلیم دیتی تھیں.وہ نمازوں میں مسلمان مردوں کے ساتھ شامل ہوتی تھیں.وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی تقریر ریریں اور خطبات سنتی تھیں.وہ قومی کاموں میں مشورہ دیتی تھیں.وہ حج میں مردوں کے پہلو بہ پہلو
مراسم حج ادا کرتی تھیں.وہ سفروں میں مردوں کے ساتھ جاتی تھیں.وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ
ضرورت پیش آنے پر ملاقات کرتی اور ان کی بات سنتیں اور اپنی بات سناتی تھیں.وہ سواری کرتی تھیں.وہ تفریحی تماشے دیکھتی تھیں.وہ جنگوں میں شریک ہوتی اور زخموں کی تیمارداری اور نرسنگ کی خدمات
سرانجام دیتی تھیں اور ضرورت پڑتی تو میدان جنگ میں تلوار بھی چلا لیتی تھیں.پس پردہ پر جتنے بھی
اعتراض ہوتے ہیں وہ در حقیقت اصل اسلامی پردہ پر نہیں ہیں.بلکہ موجودہ زمانہ کے بگڑے ہوئے پردہ
پر ہیں جس نے عورت کو گھر کی چاردیواری میں قریباً ایک حیوان کی طرح قید کر رکھا ہے.مگر اس نقص کے
دور کرنے کے یہ معنے نہیں ہیں کہ ایک انتہا سے ہٹ کر دوسری انتہا کو اختیار کر لیا جاوے کیونکہ یہ دونوں
ضلالت و ہلاکت کی راہیں ہیں اور سلامت روی کا وہی رستہ ہے جسے اسلام نے پیش کیا ہے اور جو انسانی
فطرت کی سچی آواز ہے.علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ عورت کے کام کی اصل جگہ گھر ہے جہاں اس کے ہاتھوں
میں قوم کے نونہال پلتے ہیں جن پر آئندہ چل کر قومی اور ملکی کاموں کا بوجھ پڑنا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا
نازک اور وسیع اور عظیم الشان کام ہے کہ اگر عورت صرف اسی کام کو خیر و خوبی کے ساتھ سرانجام دے اور
اس کے لئے اپنے آپ کو اہل بنائے تو اس کی توجہ کی مصروفیت کے لئے یہی کافی ہے اور اسی سے وہ
ملک وقوم کی بہترین محسنہ بن سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کام کے لئے اسلامی پردہ مد ہے نہ کہ خلاف.حضرت زینب بنت جحش کی عمر شادی کے وقت
حضرت زینب کی شادی کے بقیہ حالات پینتیس سال کی تھی.اور عرب کے حالات کے
لے ان سب باتوں کے حوالے اس کتاب میں متفرق طور پر گزر چکے ہیں اور بعض اپنے موقع پر آگے آئیں گے
: اصابه
Page 634
۶۱۹
لحاظ سے یہ عمر ایسی تھی جسے گویا ادھیڑ کہنا چاہئے.حضرت زینب ایک نہایت متقی اور پرہیز گاراور مخیر
خاتون تھیں.چنانچہ باوجود اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں صرف زینب ہی
وہ بیوی تھیں جو حضرت عائشہ کے ساتھ مقابلہ کرتی اور ان کی ہمسری کا دم بھرتی تھیں.حضرت عائشہ
ان کے ذاتی تقوی وطہارت کی بہت مداح تھیں.اور اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں نے زینب سے زیادہ
نیک عورت نہیں دیکھی.وہ بہت متقی ، بہت راست گو، بہت صلہ رحمی کرنے والی، بہت صدقہ وخیرات
کرنے والی اور نیکی اور تقرب الہی کے اعمال میں نہایت سرگرم تھیں.بس اتنی بات تھی کہ ان کی طبیعت ذرا
تیز تھی مگر تیزی کے بعد وہ جلد ہی خود نادم ہو جایا کرتی تھیں.صدقہ وخیرات میں تو ان کا یہ مرتبہ تھا کہ
حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے
فرمایا.اسرَعُكُنَّ
لِحَاقًا بِي اَطْوَلُكُنَّ يَدًا یعنی " تم میں سے جو سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے وہ میری وفات
کے بعد سب سے پہلے فوت ہو کر میرے پاس پہنچے گی.حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس سے ظاہری
ہاتھ سمجھے اور آپس میں اپنے ہاتھ نا پا کرتی تھیں.لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے
پہلے زینب بنت جحش کا انتقال ہوا تو تب جا کر ہم پر یہ راز کھلا کہ ہاتھ سے مراد صدقہ وخیرات کا ہاتھ تھا
نہ کہ ظاہری ہاتھ.جیسا کہ اندیشہ کیا جاتا تھا حضرت زینب کی شادی پر منافقین مدینہ کی طرف سے بہت اعتراضات
ہوئے اور انہوں نے بر ملا طور پر طعن کئے کہ محمدصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر کے گویا
اپنی بہو کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے.لیکن جبکہ اس شادی کی غرض ہی عرب کی اس جاہلانہ رسم کو مٹا ناتھی
تو ان مطاعن کا سننا بھی ناگزیر تھا.اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ ابن سعد اور طبری وغیرہ نے حضرت زینب بنت جحش کی شادی کے
متعلق ایک سرا سر غلط اور بے بنیا دروایت نقل کی ہے اور چونکہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
والا صفات کے خلاف اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لئے بعض مسیحی مؤرخین نے اس روایت کو نہایت
نا گوار صورت دے کر اپنی کتب کی زینت بنایا ہے.روایت یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
زینب بنت جحش کی شادی زید کے ساتھ کر دی تو اس کے بعد آپ کسی موقع پر زید کی تلاش میں ان کے
بخاری حدیث الا فک
بخاری ومسلم بحواله اصا به حالات زینب بنت جحش
مسلم جلد ۲ باب فضل عائشہ
۴ : ترندی بحوالہ زرقانی جلد ۳
Page 635
۶۲۰
مکان پر تشریف لے گئے.اس وقت اتفاق سے زید اپنے مکان پر نہیں تھے.چنانچہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر زید کو آواز دی تو زینب نے اندر سے جواب دیا کہ وہ
مکان پر نہیں ہیں اور ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہچان کر وہ لپک کر اٹھیں اور عرض کیا
یا رسول اللہ ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں.آپ اندر تشریف لے آئیں لیکن آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور واپس لوٹنے لگے مگر چونکہ حضرت زینب گھبرا کرایسی حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی
تھیں کہ ان کے بدن پر اوڑھنی نہیں تھی اور مکان کا دروازہ کھلا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر
پڑ گئی اور آپ نعوذ باللہ ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہ الفاظ گنگناتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ سُبْحَانَ
اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ مُصَرِفِ الْقُلُوبِ پاک ہے وہ اللہ جوسب بڑائی والا ہے اور پاک ہے
وہ اللہ جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں جدھر چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے.جب زید بن حارثہ واپس
آئے تو زینب نے ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا قصہ بیان کیا.اور زید کے
دریافت کرنے پر کہ آپ کیا فرماتے تھے انہوں نے آپ کے یہ الفاظ بھی بیان کئے اور کہا میں نے تو
عرض کیا تھا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں مگر آپ نے انکار فرمایا اور واپس تشریف لے گئے.یہ سن کر زید
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا یا رسول اللہ ! شاید آپ کو زینب پسند آ گئی ہے اگر
آپ پسند فرما ئیں تو میں اسے طلاق دیئے دیتا ہوں اور پھر آپ اس کے ساتھ شادی فرمالیں.آپ نے
فرمایا ” زید خدا کا تقویٰ کرو اور زینب کو طلاق نہ دو.مگر اس کے بعد زید نے زینب کو طلاق دے دی.یہ
وہ روایت ہے جو ابن سعد اور طبری وغیرہ نے اس موقع پر بیان کی ہے اور گو اس روایت کی ایسی تشریح کی
جاسکتی ہے جو چنداں قابل اعتراض نہیں رہتی مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ از سر تا پا محض غلط اور جھوٹ ہے اور
روایت و درایت ہر دو طرح سے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے.روایا تو اس قدر جاننا کافی ہے کہ اس قصہ کے
راویوں میں زیادہ تر واقدی اور عبداللہ بن عامر اسلمی کا واسطہ آتا ہے اور یہ دونوں شخص محققین کے نزدیک
بالکل ضعیف اور نا قابل اعتماد ہیں یا حتی کہ واقدی تو اپنی کذب بیانی اور دروغ بانی میں ایسی شہرت رکھتا
ہے کہ غالبا مسلمان کہلانے والے راویوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے اور اس کے مقابلہ میں وہ روایت جو ہم
نے اختیار کی ہے جس میں زید کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر زینب کی بدسلوکی کی
تہذیب التہذیب حالات واقدمی و عبد اللہ بن عامر
تہذیب التہذیب حالات واقدی وزرقانی جلدا
Page 636
۶۲۱
شکایت کرنا بیان کیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا گیا ہے
کہ ” تم خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور طلاق نہ دو.وہ بخاری کی روایت ہے جو دوست اور دشمن کے نزدیک
قرآن شریف کے بعد اسلامی تاریخ کا صحیح ترین ریکارڈ سمجھی گئی ہے اور جس کے خلاف کبھی کسی حرف گیر کو
انگشت نمائی کی جرات نہیں ہوئی.پس اصول روایت کی رو سے دونوں روایتوں کی قدر و قیمت ظاہر ہے.اسی طرح عقلاً بھی غور کیا جاوے تو ابن سعد وغیرہ کی روایت کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا
کیونکہ جب یہ بات مسلّم ہے کہ زینب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں حتی کہ آپ ہی نے
ان کے ولی بن کر زید بن حارثہ سے ان کی شادی کی تھی.اور دوسری طرف اس بات سے بھی کسی کو انکار نہیں
ہوسکتا کہ اب تک مسلمان عورتیں پر دہ نہیں کرتی تھیں بلکہ پردہ کے متعلق ابتدائی احکام حضرت زینب اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد نازل ہوئے تھے تو اس صورت میں یہ خیال کرنا کہ زینب کو
آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا صرف اس وقت اتفاقی نظر پڑ گئی اور آپ ان پر فریفتہ ہو گئے ایک صریح
اور بدیہی البطلان جھوٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا.یقیناً اس سے پہلے آپ نے ہزاروں دفعہ زینب
کو دیکھنا ہوگا اور ان کے جسم کا حسن و قبح جو کچھ بھی تھا آپ پر عیاں تھا اور گواوڑھنی کے ساتھ دیکھا اور
اوڑھنی کے بغیر دیکھنا کوئی فرق نہیں رکھتا ، لیکن جب رشتہ اس قدر قریب تھا اور پردہ کی رسم بھی نہیں تھی
اور ہر وقت کی میل ملاقات تھی تو اغلب یہ ہے کہ آپ کو کئی دفعہ انہیں بغیر اوڑھنی کے دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا
ہوگا اور زینب کا آپ کو اندر تشریف لانے کے لئے عرض کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت ان کے بدن پر
اتنے کپڑے ضرور تھے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے لئے تیار تھیں.پس جس
جہت سے بھی دیکھا جاوے یہ قصہ ایک محض جھوٹا اور بناوٹی قصہ قرار پاتا ہے جس کے اندر کچھ بھی حقیقت
نہیں اور اگر ان دلائل کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامل درجہ مقدس اور زاہدانہ زندگی کو بھی
مدنظر رکھا جاوے جو آپ کی ہر حرکت و سکون سے عیاں تھی تو پھر تو اس واہیات اور فضول روایت کا کچھ بھی
باقی نہیں رہتا اور یہی وجہ ہے کہ محققین نے اس قصہ کو قطعی طور پر جھوٹا اور بناوٹی قرار دیا ہے.مثلاً علامہ
ابن حجر نے فتح الباری میں ، علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں وضاحت
کے ساتھ اس روایت کو سراسر جھوٹا قرار دے کر اس کے ذکر تک کو صداقت کی ہتک سمجھا ہے اور یہی حال
دوسرے محققین کا ہے اور محققین پر ہی بس نہیں بلکہ ہر شخص جسے تعصب نے اندھا نہیں کر رکھا ہمارے اس بیان
صحیح بخاری کتاب التوحید
Page 637
۶۲۲
کو جو ہم نے قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کی بنا پر مرتب کر کے ہدیہ ناظرین کیا ہے اس لچر اور نا قابل التفات
قصہ پر ترجیح دے گا جسے بعض منافقین نے اپنے پاس سے گھڑ کر روایت کیا.اور مسلمان مؤرخین نے جن کا
کام صرف ہر قسم کی روایات کو جمع کرنا تھا اسے بغیر کسی تحقیق کے اپنی تاریخ میں جگہ دے دی اور پھر بعض
غیر مسلم مؤرخین نے مذہبی تعصب سے اندھا ہو کر اسے اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے.اس بناوٹی قصہ کے ضمن میں یہ بات خاص طور پر یا درکھنی چاہئے کہ یہ زمانہ اسلامی تاریخ کا وہ زمانہ تھا
جبکہ منافقین مدینہ اپنے پورے زور میں تھے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کی سرکردگی میں ان کی طرف سے
ایک با قاعدہ سازش اسلام اور بانی اسلام کو بدنام کرنے کی جاری تھی.اور ان کا یہ طریق تھا کہ جھوٹے
اور بناوٹی قصے گھڑ گھڑ کر خفیہ خفیہ پھیلاتے رہتے تھے.یا اصل بات تو کچھ ہوتی تھی اور وہ اسے کچھ کا کچھ
رنگ دے کر اور اس کے ساتھ سو قسم کے جھوٹ شامل کر کے اس کی در پردہ اشاعت شروع کر دیتے
تھے.چنانچہ قرآن شریف کی سورۃ احزاب میں جس جگہ حضرت زینب کی شادی کا ذکر ہے اس کے ساتھ
ساتھ منافقین مدینہ کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اور ان کی شرارتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے.لَبِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُخْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيْلًا " یعنی اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے
دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں جھوٹی اور فتنہ انگیز خبروں کی اشاعت کرنے والے لوگ اپنی ان
کارروائیوں سے باز نہ آئے تو پھر اے نبی ! ہم تمہیں ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں گے
اور پھر یہ لوگ مدینہ میں نہیں ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑا.اس آیت میں صریح طور پر اس قصہ کے جھوٹا ہونے کی
طرف اصولی اشارہ کیا گیا ہے.پھر جیسا کہ آگے چل کر ذکر آتا ہے اسی زمانہ کے قریب قریب حضرت
عائشہ کے خلاف بہتان لگائے جانے کا خطرناک واقعہ بھی پیش آیا اور عبد اللہ بن ابی اور اس کے بد باطن
ساتھیوں نے اس افترا کا اس قدر چر چا کیا اور ایسے ایسے رنگ دے کر اس کی اشاعت کی کہ مسلمانوں پر
ان کا عرصہ عافیت تنگ ہو گیا.اور بعض کمزور طبیعت اور نا واقف مسلمان بھی ان کے اس گندے پرو پیگنڈا
کا شکار ہو گئے.الغرض یہ زمانہ منافقوں کے خاص زور کا زمانہ تھا اور ان کا سب سے زیادہ دل پسند
حریہ یہ تھا کہ جھوٹی اور گندی خبریں اڑا اڑا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعلقین کو بد نام کریں.یہ خبریں ایسی ہوشیاری کے ساتھ پھیلائی جاتی تھیں کہ بعض اوقات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
: سورۃ احزاب : ۶۱
Page 638
۶۲۳
اکابر صحابہ و تفصیلی علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تردید کا موقع بھی نہیں ملتا تھا اور اندر ہی اندران کا زہر پھیلتا
جاتا تھا.ایسی صورتوں میں بعض بعد میں آنے والے مسلمان جو زیادہ تحقیق و تدقیق کے عادی نہیں تھے
انہیں سچا سمجھ کر ان کی روایت شروع کر دیتے تھے اور اس طرح یہ روایتیں واقدی وغیرہ کے ٹائپ کے
مسلمانوں کے مجموعہ میں راہ پا گئیں مگر جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے صحیح احادیث میں ان کا نام ونشان
تک نہیں پایا جاتا اور نہ تحقین نے انہیں قبول کیا ہے.حضرت زینب بنت جحش کے قصہ میں سرولیم میور صاحب نے جن سے یقیناً ایک بہتر ذہنیت کی امید
کی جاتی تھی واقدی کی غلط اور بناوٹی روایت کو قبول کرنے کے علاوہ اس موقع پر یہ دل آزار طعن بھی کیا ہے
کہ گویا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانی خواہشات بھی ترقی کرتی جاتی
تھیں اور آپ کے حرم کی توسیع کو میور صاحب اسی جذ بہ پر مبنی قرار دیتے ہیں.میں بہ حیثیت ایک مؤرخ
کے کسی مذہبی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا مگر تاریخی واقعات کو ایک غلط راستے پر ڈالا جاتا دیکھ کر اس ناگوار
اور غیر منصفانہ طریق کے خلاف آواز بلند کرنے سے بھی باز نہیں رہ سکتا.بے شک یہ ایک تاریخی حقیقت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کیں اور یہ بات بھی مسلمہ تاریخ کا حصہ ہے
کہ علاوہ حضرت خدیجہ کے آپ کی ساری شادیاں اس زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں جسے بڑھاپے کا زمانہ کہا
جا سکتا ہے مگر بغیر کسی تاریخی شہادت کے بلکہ صریح تاریخی شہادت کے خلاف یہ خیال کرنا کہ آپ کی یہ
شادیاں نعوذ باللہ جسمانی خواہشات کے جذبہ کے ماتحت تھیں ایک مؤرخ کی شان سے بہت بعید ہے
اور ایک شریف انسان کی شان سے بعید تر.میور صاحب اس حقیقت سے بے خبر نہیں تھے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں ایک چالیس سالہ ادھیڑ عمر کی بیوہ عورت ( حضرت خدیجہ ) سے
شادی کی اور پھر پچاس سال کی عمر تک اس رشتہ کو اس خوبی اور وفاداری کے ساتھ نباہا کہ جس کی نظیر
نہیں ملتی ہے اور اس کے بعد بھی آپ نے پچپن سال کی عمر تک عملاً صرف ایک بیوی رکھی.اور یہ بیوی
(حضرت سودة ) بھی حسن اتفاق سے ایک بیوہ اور ادھیڑ عمر کی خاتون تھیں یے اور اس تمام عرصہ میں جو
جذبات نفسانی کے ہیجان کا مخصوص زمانہ ہے آپ
کو کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا.میور صاحب اس
تاریخی واقعہ سے بھی ہر گز نا واقف نہیں تھے کہ جب مکہ والوں نے آپ کی تبلیغی مساعی سے تنگ آکر اور ان
ا اصابه ورزقانی حالات حضرت خدیجه نیز میور صفحه ۱۰۲٬۲۲
اصابه وزرقانی حالات سوده نیز میور صفحه ۱۱۰،۱۰۹
Page 639
۶۲۴
کو اپنے قومی دین کا مخرب خیال کر کے آپ کے پاس عتبہ بن ربیعہ کو بطور ایک وفد کے بھیجا اور آپ سے
پرزور استدعا کی کہ آپ اپنی ان کوششوں سے رک جائیں اور دولت اور ریاست کی طمع دینے کے علاوہ
ایک یہ درخواست بھی پیش کی کہ اگر آپ کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے ہم سے خوش ہو سکتے ہیں اور
ہمارے دین کو برا بھلا کہنے اور اس نئے دین کی تبلیغ سے باز رہ سکتے ہیں تو آپ جس لڑکی کو پسند کریں ہم
آپ کے ساتھ اس کی شادی کئے دیتے ہیں.اس وقت آپ کی عمر بھی کوئی ایسی زیادہ نہیں تھی.پھر جسمانی
طاقت بھی بعد کے زمانہ کی نسبت یقیناً بہتر حالت میں تھی.مگر جو جواب آپ نے رؤساء مکہ کے اس نمائندہ
کو دیا وہ تاریخ کا ایک کھلا ہوا ورق ہے جس کے دوہرانے کی اس جگہ ضرورت نہیں.یہ تاریخی واقعہ بھی
میور صاحب کی نظر سے اوجھل نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ آپ کو آپ کی بعثت سے قبل یعنی چالیس سال کی
عمر تک ایک بہترین اخلاق والا انسان سمجھتے تھے.نے مگر با وجود ان سب شہادات کے میور صاحب کا یہ لکھنا
کہ پچپن سال کی عمر کے بعد جب ایک طرف آپ کی جسمانی طاقتوں میں طبعا انحطاط رونما ہونے لگا
اور دوسری طرف آپ کے مشاغل اور ذمہ داریاں اس قدر بڑھ گئیں جو ایک مصروف سے مصروف انسان
کے مشاغل کو شرماتی ہیں تو آپ عیش وعشرت میں مبتلا ہو گئے ہرگز کوئی غیر متعصبانہ ریمارک نہیں سمجھا
جا سکتا ! کہنے کو تو کوئی شخص جو کچھ بھی کہنا چاہے کہ سکتا ہے اور اس کی زبان اور قلم کو روکنے کی دوسروں میں
طاقت نہیں ہوتی.مگر عقل مند آدمی کو چاہئے کہ کم از کم ایسی بات نہ کہے جسے دوسروں کی عقل سلیم تسلیم کرنے
کے لئے تیار نہ ہو.میور صاحب اور ان کے ہم خیال لوگ اگر اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی اتار کر دیکھتے
تو انہیں معلوم ہو جا تا کہ محض یہ بات ہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں آپ کے بڑھاپے کی عمر
کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جسمانی اغراض کے ماتحت نہ تھیں بلکہ ان کی تہ میں کوئی
دوسری اغراض مخفی تھیں.خصوصاً جبکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کے ایام ایک ایسی
حالت میں گزارے جس کی وجہ سے آپ نے اپنوں اور بیگانوں سے امین کا خطاب حاصل کیا.مجھے اس
بات کے مطالعہ سے ایک روحانی سرور حاصل ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کے جس زمانہ میں آپ کی یہ شادیاں
ہوئیں وہ وہ زمانہ ہے جب کہ آپ پر آپ کے فرائض نبوت کا سب سے زیادہ بار تھا اور اپنی ان لا تعداد
اور بھاری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آپ بالکل محوہور ہے تھے.اور میرے نزدیک اور میں سمجھتا ہوں کہ
سیرت حلبیہ جلد اصفحه ۳۲۳ نیز طبرانی و ابن ابی حاتم بحوالہ لباب النقول تفسیر سورۃ کافرون
: میور صفحه ۲۰،۱۸
Page 640
۶۲۵
ہر انصاف پسند شریف انسان کے نزدیک محض یہ منظر ہی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ آپ کی یہ شادیاں
آپ کے فرائض نبوت کا حصہ تھیں جو آپ نے اپنی خانگی خوشی کو برباد کرتے ہوئے تبلیغ وتربیت کی اغراض
کے ماتحت کیں.ایک برا آدمی دوسرے کے افعال میں بری نیت تلاش کرتا ہے اور اپنی گندی حالت کی وجہ
سے بسا اوقات دوسرے کی نیک نیت کو سمجھ بھی نہیں سکتا مگر ایک شریف انسان اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے
کہ بسا اوقات ایک ہی فعل ہوتا ہے جسے ایک گندہ آدمی بری نیت سے کرتا ہے مگر اسی کو ایک نیک آدمی نیک
اور پاک نیت سے کر سکتا ہے اور کرتا ہے.میں اس موقع پر یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں شادی کی
غرض یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لئے اکٹھے ہوسکیں بلکہ گو
نسل انسانی کے بقا کے لئے مرد و عورت کا اکٹھا ہونا نکاح کی ایک جائزہ غرض ہے مگر اس میں بہت سی اور
پاکیزہ اغراض بھی مدنظر ہیں.پس ایک ایسے انسان کی شادیوں کی وجہ تلاش کرتے ہوئے جس کی زندگی کا
ہر حرکت وسکون اس کی بے نفسی اور پاکیزگی پر ایک دلیل ہے.گندے آدمیوں کی طرح گندے خیالات کی
طرف مائل ہونے لگنا اس شخص کو تو ہر گز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کے متعلق رائے لگائی جاتی ہے
مگر رائے لگانے والے کے اپنے اندرونہ کا آئینہ ضرور سمجھا جاسکتا ہے.پس اس سے زیادہ میں اس
اعتراض کے جواب میں کچھ نہیں کہوں گا.والله المستعان على ما يصفون.کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میور صاحب اور مارگولیس صاحب نے اس موقع پر یہ
مفید مطلب وحی اتارلیا کرتے تھے؟
طعن بھی کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
موقع پر اپنے مفید مطلب وحی اتارلی.یعنی جب
زینب کے ساتھ شادی کی خواہش پیدا ہوئی تو اسے جائز کرنے اور لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لئے
الہام کی آڑ لے لی اور اس میں ان کا اشارہ یہ ہے کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے وحی
والہام وغیرہ نہیں ہوتے تھے بلکہ نعوذ باللہ آپ خود ہی اپنی طرف سے الہام بنا کر خدا کی طرف منسوب
کر دیتے تھے.اس سوال کے مذہبی پہلو سے تو بحیثیت مؤرخ ہونے کے میرا کوئی سروکار نہیں ہے مگر یہ
خیال تاریخی طور پر غلط اور خلاف واقعہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے مفید مطلب وحی ہو جایا
کرتی تھی.آپ کی زندگی اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ بسا اوقات آپ کی ذاتی خواہش کے
خلاف وحی نازل ہوتی تھی.چنانچہ یہی قصہ اس کی ایک روشن مثال ہے.قرآن شریف صاف فرماتا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے ساتھ شادی کرنے سے خائف تھے اور اسے حتی الوسع ٹالنا چاہتے تھے
Page 641
۶۲۶
مگر اللہ تعالیٰ نے حکماً آپ کو اس طرف مائل کیا بلکہ ایک گونہ تادیب بھی فرمائی کہ تَخْشَى النَّاسَ
وَالله أَحَى أَنْ تَخْشَهُ لا یعنی اے نبی ! تم لوگوں کی وجہ سے خائف ہو حالانکہ صرف ہم ہی اس
بات کے حق دار ہیں کہ ہم سے ڈرا جاوے.پس غور کیا جاوے تو جس قصہ کے ضمن میں میور صاحب
نے ایک جھوٹی روایت پر بنا رکھ کر یہ اعتراض اٹھایا ہے وہی اسے جھوٹا ثابت کر رہا ہے.اسی طرح
قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقوں کو
پیچھے رہنے کی اجازت دے دی تو اس پر یہ وحی الہی نازل ہوئی کہ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ
یعنی اے نبی ! خدا تمہیں معاف فرمائے تم نے انہیں کیوں اجازت دی؟ ہم تو اس موقع پر مومن
و منافق میں امتیاز پیدا کرنا چاہتے تھے.اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی
بن سلول رئیس المنافقین کا جنازہ پڑھ دیا اور آپ کی رائے تھی کہ اس میں کوئی حرج نہیں تو اس پر یہ
وحی الہی نازل ہوئی کہ لَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ " یعنی " آئندہ
ان منافقوں میں کسی کا جنازہ نہ پڑھو.اور نہ کسی کی قبر پر دعا مانگو کیونکہ دراصل وہ کافر ہیں اور خدا کی
نافرمانی کی حالت میں مرتے ہیں.اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ جب آپ نے غزوہ احد میں زخمی
ہونے پر ایسے طریق پر دعا کی جو قریش کے خلاف ایک گونہ بددعا کا رنگ تھا تو اس پر یہ قرآنی آیت
اتری کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ - یعنی تمہیں اس معاملہ سے سروکار نہیں ہونا چاہئے کہ ہم کسے
چھوڑتے اور کسے عذاب دیتے ہیں.اسی طرح جب آپ کی بیویوں کی تعداد اس حد تک پہنچ گئی جو
خدائی علم میں ضروری تھی تو آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اب اس کے بعد تمہیں کسی اور شادی کی اجازت
نہیں ہے.الغرض یہ ایک بالکل غلط اور بے بنیاد خیال ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق وحی اتار لیا
کرتے تھے اور یہ اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جو تاریخ اسلامی سے قطع نا بلد ہے.پھر زیادہ تعجب کی بات
یہ ہے کہ میور صاحب اور مارگولیس صاحب تو زینب کی شادی کے موقع پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مفید مطلب وحی اتار لی مگر حدیث میں یہ آتا ہے کہ چونکہ اس موقع پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور ارادے کے بالکل خلاف وحی نازل ہوئی تھی اس لئے اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی وحی چھپانی ہوتی تو ضرور اس وحی کو چھپاتے جو آپ کی مرضی
سورۃ احزا
۳۸ :
،،
: سورة توبة : ۴۳
: سورة توبة : ۸۴
بخاری حالات احد و کتاب التفسیر سورۃ احزاب : ۵۳
Page 642
۶۲۷
66
کے خلاف ہونے کے علاوہ ایک گونہ عتاب کا بھی رنگ رکھتی تھی.چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں
لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هذه ا یعنی اگر آنحضرت صلی الله
علیہ وسلم اپنی کسی وحی کو چھپانے والے ہوتے تو ضرور اس وحی کو چھپاتے.پس اپنے مفید مطلب وحی
اتار لینے کا اعتراض بالکل غلط اور بے بنیاد ہے.باقی رہا یہ امر کہ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے مطابق وحی نازل ہو جاتی تھی.سو یہ درست ہے مگر یہ ہرگز جائے اعتراض
نہیں بلکہ یہی بات آپ کی صداقت اور کمال کی دلیل ہے.قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یعنی اے نبی ! تو اس
خدائی دین اسلام پر راستی اور سداد کے ساتھ قائم ہو جا جس کی بناوٹ انسانی فطرت کے مطابق بنائی گئی
ہے.اور عقلاً بھی غور کیا جاوے تو یہی ہونا چاہئے تھا کہ فطرت انسانی شریعت کے مطابق بنائی
جاتی.یا بالفاظ دیگر شریعت کو فطرت انسانی کے مطابق اتارا جاتا.پس فطرت صحیحہ اور شریعت اسلامی
کا توار د تو ضروری ہے اور جتنی جتنی کسی شخص کی فطرت زیادہ صاف اور بیرونی اثرات سے زیادہ پاک ہوتی
ہے اتنا ہی وہ شریعت کی روح کے زیادہ قریب ہوتا ہے.لہذا یہ ضروری تھا کہ دوسرے انسانوں کی نسبت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طبعی میلانات شریعت اسلامی کے زیادہ قریب ہوتے.اور عام حالات میں
آپ کی رائے اسی رستے پر چلتی جس رستے پر شریعت کا نزول ہونا تھا مگر یہ بالکل درست نہیں کہ ہمیشہ ہی
ایسا ہوتا تھا کیونکہ بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور بشری لوازمات کے ماتحت ضروری
تھا کہ کہیں کہیں اختلاف بھی ہو جاتا.علاوہ ازیں چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات واضح کرنا منظور تھی کہ جو وحی
آپ پر نازل ہوتی ہے وہ آپ کے دل و دماغ سے ایک بال منبع رکھتی ہے اور ایک وراء الوراء ہستی کی
طرف سے آتی ہے.اس لئے اس نے اپنے حکیمانہ تصرف کے ماتحت ایسی مثالوں کی بھی کمی نہیں رہنے
دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کچھ تھا اور وحی کچھ اور نازل ہوئی یا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خواہش کچھ تھی اور وحی کچھ اور نازل ہوئی.پس میور صاحب اور مارگولیس صاحب کا اعتراض بالکل
غلط اور بے بنیاد ہے.غززہ بنو مصطلق اور واقعہ افک شعبان ۵ ہجری قریش کی مخالفت دن بدن زیادہ خطرناک
صورت اختیار کرتی جاتی تھی.وہ اپنی ریشہ دوانی
بخاری کتاب التوحید
: سورة روم : ۳۱
Page 643
۶۲۸
سے عرب کے بہت سے قبائل کو اسلام اور بانی اسلام کے خلاف کھڑا کر چکے تھے لیکن اب ان کی عداوت
نے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا اور وہ یہ کہ حجاز کے وہ قبائل جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے اب
وہ بھی قریش کی فتنہ انگیزی سے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے شروع ہو گئے.اس معاملہ میں پہل کرنے والا
مشہور قبیلہ بنوخزاعہ تھا جن کی ایک شاخ بنو مصطلق نے مدینہ کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے
اور ان کے رئیس حارث بن ابی ضرار نے اس علاقہ کے دوسرے قبائل میں دورہ کر کے بعض اور قبائل کو بھی
اپنے ساتھ ملالیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے مزید احتیاط کے
طور پر اپنے ایک صحابی بریدہ بن حصیب نامی کو دریافت حالات کے لئے بنو مصطلق کی طرف روانہ فرمایا اور
ان کو تاکید فرمائی کہ بہت جلد واپس آکر حقیقتہ الا مر سے آپ کو اطلاع دیں.بریدہ گئے تو دیکھا کہ واقعی
ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور نہایت زور شور سے مدینہ پر حملہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں.انہوں نے فورا واپس
آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے اور آپ نے حسب عادت مسلمانوں کو پیش بندی کے طور پر
دیار بنو مصطلق کی طرف روانہ ہونے کی تحریک فرمائی اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے
بلکہ ایک بڑا گر وہ منافقین کا بھی جو اس سے پہلے اتنی تعداد میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے ساتھ ہو گیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ابوذر غفاری نے یا بعض روایات کی رو سے زید بن حارثہ کے کو مدینہ کا
امیر مقرر کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے شعبان ۵ ہجری میں مدینہ سے نکلے.فوج میں صرف تمہیں گھوڑے
تھے.البتہ اونٹوں کی تعداد کسی قدر زیادہ تھی اور انہی گھوڑوں اور اونٹوں پر مل جل کر مسلمان باری باری سوار
ہوتے تھے.راستہ میں مسلمانوں کو کفار کا ایک جاسوس مل گیا جسے انہوں نے پکڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر کیا اور آپ نے اس تحقیق کے بعد کہ وہ واقعی جاسوس ہے اس سے کفار کے متعلق کچھ
حالات وغیرہ دریافت کرنے چاہے مگر اس نے بتانے سے انکار کیا اور چونکہ اس کا رویہ مشتبہ تھا اس لئے
مروجہ قانون جنگ کے ماتحت حضرت عمرؓ نے اسے قتل کر دیا.اور اس کے بعد لشکر اسلام آگے روانہ ہوا.بنو مصطلق کو جب مسلمانوں کی آمد آمد کی اطلاع ہوئی اور یہ خبر بھی پہنچی کہ ان کا جاسوس مارا گیا ہے تو وہ
بہت خائف ہوئے کیونکہ اصل منشا ان کا یہ تھا کہ کسی طرح مدینہ پر اچانک حملہ کرنے کا موقع مل جاوے
میور صفحه ۲۸۶
: ابن ہشام وابن سعد
ابن سعد
۵ : ابن سعد
: ابن سعد
ابن ہشام
ك: ابن سعد
: ابن سعد وزرقانی جلد ۲ صفحه ۹۶
: ابن سعد وزرقانی
Page 644
۶۲۹
مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی کی وجہ سے اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے.پس وہ بہت
مرعوب ہو گئے اور دوسرے قبائل جوان کی مدد کے لئے ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے وہ تو خدائی تصرف کے
ماتحت کچھ ایسے خائف ہوئے کہ فوراً ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے لے مگر خود بنو مصطلق
کو قریش نے مسلمانوں کی دشمنی کا کچھ ایسا نشہ پلا دیا تھا کہ وہ پھر بھی جنگ کے ارادے سے باز نہ آئے
اور پوری تیاری کے ساتھ اسلامی لشکر کے مقابلہ کے لئے آمادہ رہے.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مریسیع میں پہنچے جس کے قریب بنو مصطلق کا قیام تھا اور جو ساحل سمندر کے قریب مکہ اور مدینہ کے درمیان
ایک مقام کا نام ہے تو آپ نے ڈیرہ ڈالنے کا حکم دیا اور صف آرائی اور جھنڈوں کی تقسیم وغیرہ کے بعد آپ
نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر بنو مصطلق میں یہ اعلان کریں کہ اگر اب بھی وہ اسلام کی عداوت سے
باز آجائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیں تو ان کو امن دیا جائے گا اور مسلمان واپس
لوٹ جائیں گے مگر انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کیا اور جنگ کے واسطے تیار ہو گئے یا حتی کہ لکھا ہے کہ
سب سے پہلا تیر جو اس جنگ میں چلایا گیا وہ انہی کے آدمی نے چلایا.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے بھی صحابہ کولڑنے کا حکم دیا.تھوڑی دیر تک فریقین کے درمیان
خوب تیز تیراندازی ہوئی.جس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیکلخت دھاوا کر دینے کا
حکم دیا اور اس اچانک دھاوے کے نتیجے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے مگر مسلمانوں نے ایسی ہوشیاری
کے ساتھ ان کا گھیرا ڈالا کہ ساری کی ساری قوم محصور ہو کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوگئی اور صرف دس کفار اور
ایک مسلمان کے قتل پر اس جنگ کا جو ایک خطرناک صورت اختیار کرسکتا تھا خاتمہ ہو گیا ہے
اس موقع پر یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اسی غزوہ کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مصطلق پر ایسے وقت میں حملہ کیا تھا کہ وہ غفلت کی حالت میں اپنے جانوروں کو پانی پلا
رہے تھے.مگر غور سے دیکھا جاوے تو یہ روایت مؤرخین کی روایت کے خلاف نہیں ہے بلکہ درحقیقت
یہ دور واسیتیں دو مختلف وقتوں سے تعلق رکھتی ہیں یعنی واقع یوں ہے کہ جب اسلامی لشکر بنو مصطلق کے قریب
پہنچا تو اس وقت چونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمان بالکل قریب آگئے ہیں ( گوانہیں اسلامی لشکر کی
آمد آمد کی اطلاع ضرور ہو چکی تھی وہ اطمینان کے ساتھ ایک بے ترتیبی کی حالت میں پڑے تھے اور
ابن سعد
: زرقانی حالات غزوہ مریسیع
ابن سعد
ه بخاری کتاب العتق
: زرقانی
Page 645
۶۳۰
اسی حالت کی طرف بخاری کی روایت میں اشارہ ہے لیکن جب ان کو مسلمانوں کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو
وہ اپنی مستقل سابقہ تیاری کے مطابق فور أصف بند ہو کر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے اور یہ وہ حالت ہے جس
کا ذکر مؤرخین نے کیا ہے.اس اختلاف کی یہی تشریح علامہ ابن حجر اور بعض دوسرے محققین نے کی ہے
اور یہی درست معلوم ہوتی ہے.جنگ کے اختتام کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تک مریسیع میں قیام فرمایا مگر اس
قیام کے درمیان منافقین کی طرف سے ایک ایسا نا گوار واقعہ پیش آیا جس سے قریب تھا کہ کمزور مسلمانوں
میں خانہ جنگی تک نوبت پہنچ جاتی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع شناسی اور مقناطیسی اثر نے اس فتنہ
کے خطرناک نتائج سے مسلمانوں کو بچالیا.واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عمر کا ایک نوکر چہجاہ نامی مریسیع کے
مقامی چشمہ پر سے پانی لینے کے لئے گیا.اتفاقاً اسی وقت ایک دوسرا شخص سنان نامی بھی جو انصار کے
حلیفوں میں سے تھا پانی لینے کے لئے وہاں پہنچا.یہ دونوں شخص جاہل اور عامی لوگوں میں سے تھے.چشمہ پر یہ دونوں شخص آپس میں جھگڑ پڑے اور جاہ نے سنان کو ایک ضرب لگا دی.پس پھر کیا تھا سنان نے
زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ اے انصار کے گروہ! میری مدد کو پہنچو کہ میں پٹ گیا.جب چہجاہ نے دیکھا
کہ سنان نے اپنی قوم کو بلایا ہے تو اس نے بھی اپنی قوم کے لوگوں
کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے مہاجرین
بھا گیو دوڑ یو کے جن انصار و مہاجرین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی وہ اپنی تلوار میں لے کر بے تحاشا اس
چشمہ کی طرف لپکے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک اچھا خاصہ مجمع ہو گیا اور قریب تھا کہ بعض جاہل نو جوان
ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے مگر اتنے میں بعض سمجھدار اور مخلص مہاجرین وانصار بھی موقع پر پہنچ گئے
اور انہوں نے فور لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے صلح صفائی کروادی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر
پہنچی تو آپ نے فرمایا.یہ ایک جاہلیت کا مظاہرہ ہے اور اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا." اور اس طرح
معاملہ رفع دفع ہوگیا لیکن جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو اس غزوہ میں شامل تھا اس
واقعہ کی اطلاع پہنچی تو اس بدبخت نے اس فتنہ کو پھر جگانا چاہا اور اپنے ساتھیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ اکسایا.اور کہا یہ سب تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم نے ان بے خانماں
زرقانی جلد ۲ صفحه ۹۸
: ترندی تفسیر سورۃ منافقون وابن ہشام وابن سعد حالات غزوہ مریسیع
: ابن سعد
بخاری و ترمندی تفسیر سورة منافقون
Page 646
۶۳۱
مسلمانوں کو پناہ دے کر ان کو سر پر چڑھا لیا ہے.اب بھی تمہیں چاہئے کہ ان کی اعانت سے دست
بردار ہو جاؤ پھر یہ خود بخود چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے اور بالآخر اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ
لَبِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ.یعنی ”دیکھو تو اب مدینہ میں جاکر
عزت والا شخص یا گروہ ذلیل شخص یا گروہ کو اپنے شہر سے باہر نکال دیتا ہے یا نہیں ؟.اس وقت ایک مخلص
مسلمان بچہ زید بن ارقم بھی وہاں بیٹھا تھا اس نے عبداللہ کے منہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
یہ الفاظ سنے تو بے تاب ہو گیا.اور فوراً اپنے چا کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع
دی.اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمرؓ بھی بیٹھے تھے.وہ یہ الفاظ سن کر غصہ وغیرت
سے بھر گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ! آپ مجھے اجازت دیں کہ میں
اس منافق فتنہ پرداز کی گردن اڑا دوں.آپ نے فرمایا ”عمر ! جانے دو.کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ
لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا پھرتا ہے.پھر آپ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے
ساتھیوں کو بلوا بھیجا اور ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے.وہ سب قسمیں کھا گئے کہ ہم نے کوئی
ایسی بات نہیں کی ہے بعض انصار نے بھی بطریق سفارش عرض کیا کہ زید بن ارقم کو غلطی لگی ہوگی تے آپ
نے اس وقت عبداللہ بن اُبی اور اس کے ساتھیوں کے بیان کو قبول فرمالیا اور زید کی بات رد کر دی جس سے
زید کو سخت صدمہ ہوا مگر بعد میں قرآنی وحی نے زید کی تصدیق فرمائی اور منافقین کو جھوٹا قرار دیا ہے ادھر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو بلا کر اس بات کی تصدیق شروع فرما دی اور اُدھر
آپ نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اسی وقت لوگوں کو کوچ کا حکم دے دو.یہ وقت دو پہر کا تھا جبکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے کیونکہ عرب کے موسم کے لحاظ سے یہ وقت سخت
گرمی کا وقت ہوتا ہے اور اس میں سفر کرنا نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے مگر آپ نے اس وقت کے حالات کے
مطابق یہی مناسب خیال فرمایا کہ ابھی کوچ ہو جاوے.چنانچہ آپ کے حکم کے ماتحت فور اسا را اسلامی لشکر
واپسی کے لئے تیار ہو گیا.غالباً اسی موقع پر اسید بن حضیر انصاری جو قبیلہ اوس کے نہایت نامور رئیس تھے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا.یا رسول اللہ ! آپ تو عموماً ایسے وقت
ا بخاری و ترمذی تفسیر سورۃ منافقون وا بن ہشام اوبن سعد حالات مریسیع
بخاری و ترمذی
سورة منافقون و بخاری و ترندی
ابن ہشام
ه: ابن سعد
Page 647
۶۳۲
میں سفر
نہیں فرمایا کرتے آج کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا.اسید! کیا تم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن اُبی نے
کیا الفاظ کہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مدینہ چل لیں.وہاں پہنچ کر عزت والا شخص ذلیل شخص کو باہر نکال
دے گا.‘ اسید نے بے ساختہ عرض کیا.ہاں یا رسول اللہ آپ چاہیں تو بے شک عبد اللہ کو مدینہ سے باہر نکال
سکتے ہیں کیونکہ واللہ عزت والے آپ ہیں اور وہی ذلیل ہے.پھر اسید بن حضیر نے عرض کیا یا رسول اللہ !
آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تشریف لانے سے قبل عبد اللہ بن ابی اپنی قوم میں بہت معز تھا اور اس کی
قوم اس کو اپنا بادشاہ بنانے کی تجویز میں تھی جو آپ کے تشریف لانے سے خاک میں مل گئی.پس اسی وجہ
سے اس کے دل میں آپ کے متعلق حسد بیٹھ گیا ہوا ہے.اس لئے اس کی بکواس کی کچھ پروا نہ کریں اور
اس سے درگز رفرما دیں یا تھوڑی دیر میں عبداللہ بن اُبی کا لڑکا جس کا نام حباب تھا مگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبداللہ کر دیا تھا اور وہ ایک بہت مخلص صحابی تھا گھبرایا ہوا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا.یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کی گستاخی
اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم دینا چاہتے ہیں.اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو آپ مجھے حکم
فرمائیں میں ابھی اپنے باپ کا سرکاٹ کر آپ کے قدموں میں لا ڈالتا ہوں مگر آپ کسی اور کو ایسا ارشاد نہ
فرمائیں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی جاہلیت کی رگ میرے بدن میں جوش مارے اور میں اپنے باپ کے
قاتل کو کسی وقت کوئی نقصان پہنچا بیٹھوں اور خدا کی رضا چاہتا ہوا بھی جہنم میں جاگروں.آپ نے
اسے تسلی دی اور فرمایا کہ ہمارا ہر گز یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ ہم بہر حال تمہارے والد کے ساتھ نرمی اور احسان
کا معاملہ کریں گے.مگر عبد اللہ بن عبداللہ بن ابی کو اپنے باپ کے خلاف اتنا جوش تھا کہ جب لشکر اسلامی
مدینہ کی طرف لوٹا تو عبد اللہ اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم ! میں تمہیں
واپس نہیں جانے دوں گا جب تک تم اپنے منہ سے یہ اقرار نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں
اور تم ذلیل ہوا اور عبداللہ نے اس اصرار سے اپنے باپ پر زور ڈالا کہ آخر اس نے مجبور ہوکر یہ الفاظ کہہ
دیئے جس پر عبداللہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا.کے
جب واپسی کا کوچ شروع ہوا تو اس دن کا بقیہ حصہ اور ساری رات اور اگلے دن کا ابتدائی حصہ لشکر
اسلامی برابر لگا تار چلتا رہا اور جب بالآخر ڈیرہ ڈالا گیا تو لوگ اس قدر تھک کر چور ہو چکے تھے کہ مقام
کرتے ہی ان میں سے اکثر گہری نیند سو گئے." اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی
ابن ہشام : ابن ہشام وطبری
ترمذی و ابن سعد
ابن ہشام
Page 648
۶۳۳
سے لوگوں کی توجہ اس نا گوار واقعہ کی طرف سے ہٹ کر ایک لمبے وقفہ تک دوسری طرف لگی رہی اور اللہ تعالیٰ
نے اپنے فضل سے مسلمانوں
کو منافقین کی فتنہ انگیزی سے بچالیا.دراصل منافقین مدینہ کی ہمیشہ یہ
کوشش رہتی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں میں خانہ جنگی اور باہمی انشقاق کی صورت پیدا
کر دیں.نیز اگر ممکن ہو تو ان کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کر دیں.مگر اسلام
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقناطیسی شخصیت نے مسلمانوں میں ایسا رشتہ اتحاد پیدا کر دیا تھا کہ کوئی
سازش اس میں رخنہ انداز نہیں ہو سکتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تو مسلمانوں کے
دلوں میں عزت و احترام اخلاص و ایمان اور محبت و عشق کے وہ جذبات راسخ ہو چکے تھے کہ انہیں متزلزل
کرنا کسی بشر کی طاقت میں نہیں تھا.چنانچہ اسی موقع پر دیکھ لو کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے دوعامی
مسلمانوں کے ایک وقتی جھگڑے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح صحابہ میں اختلاف و انشقاق کا
بیج بونے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و رعب کو صدمہ پہنچانے کی کوشش کی.مگر اسے کیسے نا کامی کا
منہ دیکھنا پڑا اور خدا نے اسے خود اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے وہ ذلت کا پیالہ پلایا جو اسے غالباً مرتے
دم تک نہ بھولا ہوگا.واقعہ افک مگر نہ معلوم منافقین مدینہ کی مٹی میں کس فتنہ کا خمیر تھا کہ کوئی واقعہ ان کی آنکھوں کو نہ کھولتا
تھا بلکہ ہر نا کامی ان کی شرارت اور فتنہ پردازی کو اور بھی زیادہ کر دیتی تھی.چنانچہ اسی سفر
کی واپسی میں ان کی طرف سے ایک اور خطرناک فتنہ کھڑا کیا گیا جو اپنی نوعیت اور مفسدانہ اثر کے لحاظ
سے اس فتنہ سے بھی بہت زیادہ خطر ناک تھا جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے.یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ
پر تہمت لگائے جانے کا واقعہ ہے جو اسی غزوہ کے سفر واپسی میں پیش آیا.یہ تہمت اسی نوعیت کی تھی
جیسی کہ حضرت عیسی" کی والدہ حضرت مریم اور رام چندر جی کی بیوی سیتا پر بد باطن لوگوں نے لگائی اور
بہتر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کے اپنے الفاظ میں اسے بیان کیا جاوے کیونکہ وہ ایک بہت
مفصل اور دلچسپ بیان ہے جس سے اصل واقعہ کے متعلق یقینی علم حاصل ہونے کے علاوہ اس زمانہ کے
تمدن اور طریق واطوار پر بھی بہت روشنی پڑتی ہے.چنانچہ بخاری میں حضرت عائشہ کی طرف سے جو
روایت بیان ہوئی ہے اس کے ضروری ضروری اقتباسات درج ذیل کئے جاتے ہیں.حضرت عائشہ
بخاری کتاب المغازی باب غزوہ بنی مصطلق وابن ہشام وطبری وابن سعد
Page 649
۶۳۴
روایت کرتی ہیں کہ :
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جب آپ کسی سفر پر جانے لگتے تھے تو اپنی ازواج میں
قرعہ ڈالتے تھے پھر جس کا نام نکلتا تھا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے.ایک دفعہ آپ نے ایک غزوہ کے
موقع پر اسی طرح قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا.چنانچہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے گئے.یہ اس زمانہ کی بات ہے
کہ جب پردہ کے احکام نازل ہو چکے تھے.چنانچہ اس سفر میں میں ہودہ کے
اندر بیٹھتی تھی اور لوگ میرے
ہودہ کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور جہاں قیام کرنا ہوتا تھا وہاں میرے ہودہ کو اتار کر نیچے رکھ
دیتے.جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچے
تو ایک دن آپ نے رات کے وقت کوچ کا حکم دیا.جب میں نے یہ اعلان سنا تو میں حوائج انسانی سے
فارغ ہونے کے لئے لشکر سے باہر نکل کر ایک طرف کو گئی اور فارغ ہو کر واپس لوٹ آئی.جب میں اپنے
اونٹ کے قریب پہنچی تو میں نے معلوم کیا کہ میرے گلے کا ہار ندارد ہے.اس کی تلاش میں میں پھر واپس
آگئی اور اس تلاش میں مجھے کچھ دیر ہو گئی.اس اثنا میں وہ لوگ جو میرا ہودہ اٹھانے پر متعین تھے آئے اور یہ
خیال کر کے کہ میں ہودہ کے اندر ہوں انہوں نے میرا ہودہ اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور لشکر کے ساتھ
روانہ ہو گئے.چونکہ اس زمانہ میں بوجہ کم خوری اور تنگی معیشت کے عورتیں بہت دبلی پتلی ہوتی تھیں اور ان
کے بدنوں پر گوشت نہیں آتا تھا اس لئے ہودہ اٹھانے والوں کو ہودہ کے ہلکا ہونے کا شبہ نہیں گزرا اور پھر
میری عمر بھی اس وقت بہت چھوٹی تھی.بہر حال جب میں ہار کی تلاش کر لینے کے بعد واپس آئی تو کیا دیکھتی
ہوں کہ لشکر جاچکا ہے اور میدان خالی پڑا ہے.میں سخت پریشان ہوئی مگر میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اپنی
جگہ پر ٹھہرے رہنا چاہئے کیونکہ جب لوگوں کو میرے پیچھے رہ جانے کا علم ہوگا تو وہ ضرور واپس آئیں گے.پس میں اپنی جگہ پر جا کر واپس بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی.اب واقعہ یوں ہوا کہ صفوان بن معطل
ایک صحابی تھا جس کی ڈیوٹی یہ مقرر تھی کہ وہ لشکر اسلامی کے پیچھے پیچھے رہتا تھا.( تا کہ گری پڑی چیز
وغیرہ کی حفاظت ہو سکے ) وہ جب پیچھے سے آیا اور صبح کے قریب میری جگہ پر پہنچا تو اس نے مجھے وہاں
اکیلے سوئے ہوئے دیکھا.اور چونکہ وہ پردہ کے احکام کے نازل ہونے سے قبل مجھے دیکھ چکا تھا اس نے
مجھے فوراً پہچان لیا.جس پر اس نے گھبرا کر اِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رُجِعُوْنَ کہا یا اس کی اس آواز سے میں
جاگ اٹھی اور میں نے اسے دیکھتے ہی جھٹ اپنا منہ اپنی اوڑھنی سے ڈھانک لیا اور خدا کی قسم اس نے
لے : یعنی ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹیں گے.یہ کلمہ مسلمان مصیبت کے موقع پر کہا کرتے ہیں.
Page 650
۶۳۵
میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے اس کلمہ کے سوا اس کے منہ سے کوئی اور الفاظ سنے.اس کے
بعد وہ اپنے اونٹ کو آگے لایا اور میرے قریب اسے بٹھا دیا اور اس نے اونٹ کے دونوں گھٹنوں پر اپنا
پاؤں رکھ دیا ( تا کہ وہ اچانک نہ اٹھ سکے ) چنانچہ میں اونٹ کے اوپر سوار ہوگئی اور صفوان اس کے آگے
آگے اس کی مہار تھامے ہوئے چلنے لگ گیا حتی کہ ہم چلتے چلتے اس جگہ آپہنچے جہاں لشکر اسلامی ڈیرہ ڈالے
ہوئے تھا.بس یہ وہ قصہ ہے جس پر ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ہلاک ہونا تھا.اور اس بہتان کا
بانی مبانی عبد اللہ بن ابی بن سلول (رئیس المنافقین ) تھا..اس کے بعد ہم لوگ مدینہ میں پہنچ گئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ میں وہاں جاتے ہی بیمار ہوگئی اور برابر
ایک ماہ تک بیمار رہی اور اس عرصہ میں لوگوں میں بہتان لگانے والوں کی باتوں کے متعلق بہت چرچا رہا
اور ہر طرح کی چہ میگوئی ہوتی رہی مگر اس وقت تک مجھے اس تہمت کے متعلق قطعاً کوئی خبر نہیں تھی.البتہ یہ
بات ضرور تھی کہ مجھے اس بیماری کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ شفقت و مہربانی
نظر نہیں آتی تھی جو آپ عموماً مجھ پر فرمایا کرتے تھے اور اس کا مجھے سخت قلق تھا.رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاس آتے تھے تو بس سلام کہہ کر صرف اتنی بات فرماتے تھے کہ اب کیا حال ہے؟ اور پھر لوٹ
جاتے تھے اور آپ کے اس طریق سے مجھے دل ہی دل میں سخت تکلیف ہوتی تھی.میں اسی بے خبری کی
حالت میں پڑی رہی حتی کہ میری بیماری نے مجھے سخت نڈھال اور کمزور کر دیا.انہی ایام میں مجھے ایک دن
ایک عورت ام مسطح سے جو دور سے ہماری رشتہ دار بھی تھی اتفاقی طور پر بہتان لگانے والوں کا قصہ معلوم
ہوا.اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان الزام لگانے والوں میں ام مسطح کا لڑکا مسطح بھی شامل تھا.جب میں نے
کالڑ
یہ باتیں سنیں تو مجھے تو گویا اپنی اصل بیماری بھول کر ایک نئی بیماری لگ گئی.اس کے بعد جب آنحضرت
اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت تشریف لا کر یہ دریافت فرمایا کہ اب کیا حال ہے؟ تو میں نے آپ
سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ! مجھے آپ اجازت دیں تو میں چند دن کے لئے اپنے ماں باپ کے گھر چلی
جاؤں.آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی.اس سے دراصل میرا منشا یہ تھا
کہ والدین کے گھر جا کر میں اس خبر کے متعلق تحقیق کروں گی کہ کیا واقعی میرے متعلق اس قسم کی باتیں کی
جارہی ہیں.چنانچہ میں نے وہاں جا کر اپنی والدہ سے دریافت کیا.میری ماں نے کہا بیٹی ! تو پریشان نہ
ہو.یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک
کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے تو ایسی عورت کے متعلق دوسری عورتیں خواہ نخواہ باتیں بنانے لگ جاتی ہیں.
Page 651
۶۳۶
میں نے بے اختیار ہو کر کہا.سبحان اللہ سبحان اللہ ! کیا لوگ میرے متعلق واقعی یہ باتیں کر رہے ہیں؟
پھر میں رونے لگ گئی اور ساری رات میرے آنسو نہیں تھے اور نہ میں سوئی اور جب صبح ہوئی تو اس وقت
بھی میرے آنسو جاری تھے.اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو مشورہ کے لئے بلایا
کیونکہ وحی کے نزول میں بہت وقفہ پڑ گیا تھا ( اور آپ اس معاملہ میں بہت فکر مند تھے ) آپ نے ان
دونوں سے میرے متعلق مشورہ پوچھا کہ ان حالات میں کہ اس قسم کی باتیں کی جارہی ہیں مجھے کیا کرنا
چاہئے.آیا میں عائشہ سے قطع تعلق کرلوں؟ اسامہ نے عرض کیا یا رسول
اللہ!عائشہ آپ کی بیوی ہیں
(یعنی خدا تعالیٰ نے جو عائشہ کو آپ کی بیوی بننے کے لئے چنا ہے تو انہیں اس کا اہل جان کر چنا ہے ) اور
خدا کی قسم ہم تو عائشہ کے متعلق سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں جانتے مگر علی نے ( آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے ) یہ جواب دیا کہ 'یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں فرمائی اور
عائشہ کے سوا عورتوں کی کمی بھی نہیں ہے (مگر میں اصل واقعہ کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا ) آپ گھر کی خادمہ
سے دریافت فرمالیں شائد اسے کچھ علم ہو.اور وہ صحیح صحیح بات بتا سکے.اس پر آپ نے اپنی خادمہ بریرہ
کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے کسی قسم کا شبہ پیدا
ہوتا ہو؟ بریرہ نے جواب دیا کہ ”مجھے خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں
نے اپنی بی بی میں کوئی بری بات نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ خوردسالی کی وجہ سے وہ کسی قدر بے پروا
ضرور ہیں.چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندھا ہوا کھلا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آتی ہے اور
آٹا کھا جاتی ہے.پھر اسی دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک تقریر کی اور فرمایا کہ ” مجھے میرے اہل کے
بارے میں بہت دکھ دیا گیا ہے.کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس کا سد باب کر سکے؟ اور خدا کی قسم مجھے تو اپنی
بیوی کے متعلق سوائے خیر و نیکی کے اور کوئی علم نہیں ہے.اور جس شخص کا اس معاملہ میں نام لیا جاتا ہے اسے
بھی میں اپنے علم میں نیک خیال کرتا ہوں.اور وہ کبھی میرے گھر میں میری غیر حاضری میں نہیں آیا.“
آپ کی اس تقریر کوسن کر سعد بن معاذ رئیس قبیلہ اوس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا.یا رسول اللہ ! میں اس کا
سد باب کرتا ہوں.اگر تو یہ شخص ہمارے قبیلے میں سے ہے تو ہمارے نزدیک وہ واجب القتل ہے.ہم
ابھی اس کی گردن اڑائے دیتے ہیں اور اگر وہ ہمارے بھائیوں یعنی قبیلہ خزرج میں سے ہے تو پھر بھی جس
Page 652
۶۳۷
طرح آپ حکم فرمائیں ہم کرنے کو تیار ہیں.اس پر قبیلہ خزرج کے رئیس سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور وہ
ایک صالح آدمی تھے مگر اس وقت انہیں جاہلانہ غیرت آگئی اور وہ سعد بن معاذ کو مخاطب ہوکر کہنے
لگے.تم نے جھوٹ کہا ہے.خدا کی قسم !تم ہر گز ہمارے کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکو گے اور نہ تم میں یہ طاقت
ہے کہ ایسا کرو اور اگر وہ تمہارے قبیلہ میں سے ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے.اس پر اسید بن حضیر رئیس اوس
جو سعد بن معاذ کے چچازاد بھائی تھے اٹھے اور سعد بن عبادہ سے کہنے لگے کہ سعد بن معاذ جھوٹا نہیں ہے
بلکہ تم جھوٹے ہو اور تم منافق ہو کہ منافقوں کی طرف سے ہو کر لڑتے ہو.ان باتوں سے اوس وخزرج
کے بعض لوگوں کو جوش آ گیا اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جاتی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی تک
منبر پر ہی تشریف رکھتے تھے سمجھا بجھا کر سب کو ٹھنڈا کیا اور پھر آپ منبر سے اتر کر گھر تشریف لے گئے اور
میرا بدستور وہی حال تھا کہ آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے اور نیند حرام ہورہی تھی اور برابر دورات اور ایک دن
میرا یہی حال رہا اور میں سمجھتی تھی کہ میرا جگر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا.اسی حالت میں میں اپنے والدین کے پاس بیٹھی ہوئی اور ہی تھی کہ ایک انصاری عورت اجازت لے
کر اندر آئی اور میرے پاس بیٹھ کر ہمدردی کے طریق پر وہ بھی رونے لگ گئی.ہم اسی حالت میں تھے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس آکر بیٹھ گئے اور یہ پہلا دن تھا کہ آپ اس اتہام
کے بعد میرے پاس بیٹھے تھے اور ایک مہینہ ہو گیا تھا کہ میرے متعلق کوئی خدائی وحی نازل نہیں ہوئی تھی.رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہوئے کلمہ تشہد پڑھا اور خدا کو یا د کیا.پھر مجھے مخاطب ہوکر فرمانے لگے
عائشہ ! مجھے تمہارے متعلق اس قسم کی باتیں پہنچی ہیں.اگر تو تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے کہ خدا ضرور تمہاری
بریت ظاہر فرمائے گا اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو تمہیں چاہئے کہ خدا سے مغفرت مانگو اور اس کی
طرف جھکو کیونکہ جب بندہ خدا کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوا جھک جاتا ہے تو خدا اس کی تو بہ کو
قبول کرتا اور اس پر رحم فرماتا ہے.جب رسول اللہ نے یہ تقریر فرمائی تو میں نے دیکھا کہ میرے آنسو بالکل
خشک ہو گئے اور ان کا نام ونشان تک نہ رہا.اس وقت میں نے اپنے والد اور والدہ سے کہا کہ آپ
رسول اللہ سے اس بات کا جواب عرض کریں.انہوں نے کہا ” خدا کی قسم ہمیں تو کچھ نہیں سوجھتا کہ ہم کیا
جواب دیں.اس وقت میں ایک کم عمر لڑ کی تھی اور مجھے قرآن بھی زیادہ نہیں آتا تھا مگر والدین کی طرف
سے مایوس ہو کر میں نے خود آپ سے عرض کیا کہ خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں
کو وہ باتیں پہنچی
ہیں جو بعض لوگ میرے متعلق کر رہے ہیں اور آپ کے دل پر ان باتوں کا اثر ہے.پس اگر میں یہ کہوں کہ میں
Page 653
۶۳۸
بے گناہ ہوں تو آپ میری بات میں شک کریں گے اور اگر میں اپنے آپ کو اس معاملہ میں گناہ گار مان لوں
حالانکہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ مجھے سچا جانیں گے.خدا کی قسم مجھے تو اپنا معاملہ
یوسف کے باپ کا سا نظر آتا ہے جس نے یہ کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى
مَا تَصِفُونَ.” پس میرے لئے بھی صبر ہی بہتر ہے اور میں صرف خدا ہی کی مدد چاہتی ہوں ان باتوں کے
متعلق جو یہ لوگ کر رہے ہیں.یہ کہہ کر میں اپنی جگہ پر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی اور اس وقت
میرے دل میں یہ یقین تھا کہ میں چونکہ بے گناہ ہوں اللہ تعالیٰ ضرور جلد میری بریت ظاہر فرمائے گا.مگر
مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میری بریت میں کوئی قرآنی وحی نازل ہوگی اور خدا تعالیٰ اپنے صریح کلام میں
میرے بے گناہ ہونے کو ظاہر فرمائے گا بلکہ میں سمجھتی تھی کہ شائد اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو کوئی رؤیا وغیرہ دکھائی جاوے مگر خدا کی قسم آپ ابھی اس مجلس سے اٹھنے نہیں پائے تھے اور نہ گھر کا کوئی
اور شخص اٹھ کر باہر گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالت طاری ہوگئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی
اور باوجو د سردی کے آپ کے چہرہ سے پسینہ کے قطرے ٹیکنے لگ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ حالت جاتی
رہی اور آپ نے تبسم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ! خدا نے تمہاری بریت ظاہر فرما دی
ہے.جس پر میری ماں بے اختیار ہو کر بولیں عائشہ ! اٹھو! اور رسول اللہ کا شکر یہ ادا کرو.“ ( میرا دل چونکہ
اس وقت خدا کے شکر سے
لبریز تھا ) میں نے کہا میں کیوں آپ کا شکریہ ادا کروں.میں تو صرف اپنے رب
کی شکر گزار ہوں جس نے میری بریت ظاہر فرمائی ہے.اس وقت سورۃ نور کی وہ دس آیات نازل ہوئی
تھیں جو اِنَّ الَّذِينَ جَاء وَ بِالْإِفْكِ سے شروع ہوتی ہیں.جب میری بریت ظاہر ہوگئی تو میرے والد ابو بکر نے جو بوجہ غربت اور رشتہ داری کے مسطح بن اثاثہ کی
با قاعدہ امداد کیا کرتے تھے قسم کھائی کہ جب مسطح نے عائشہ پر جھوٹا اتہام باندھنے میں حصہ لیا ہے تو میں
آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا.مگر اس پر جلد ہی یہ خدائی وحی نازل ہوئی کہ ایسا کرنا بالکل پسند یدہ نہیں ہے
جس پر ابوبکر نے وہ وظیفہ پھر جاری کر دیا بلکہ یہ عہد کیا کہ آئندہ میں کبھی یہ وظیفہ بند نہیں کروں گا نیز جبکہ
ابھی تک میری بریت ظاہر نہیں ہوئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق زینب بنت جحش کی
رائے بھی دریافت کی تھی اور زینب نے یہ جواب دیا تھا کہ "یا رسول اللہ ! میں تو عائشہ کو ایک نیک اور متقی
عورت سمجھتی ہوں.حالانکہ رسول اللہ کی تمام بیویوں میں سے زینب ہی وہ بیوی تھیں جو میرا مقابلہ کرتیں
اور مجھ سے رقابت سے پیش آتی تھیں.مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بوجہ ان کی پر ہیز گاری کے اس گناہ کے
Page 654
۶۳۹
گڑھے میں گرنے سے بچالیا.میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ طویل روایت اس خیال سے درج کی ہے کہ اول تو اس معاملہ میں
یہ روایت ساری روایتوں سے مفصل اور مربوط ہے اور جو باتیں دوسرے راویوں کی روایات سے الگ
الگ ٹکڑوں کی صورت میں ملتی ہیں وہ اس روایت میں یکجا طور پر جمع ہیں.علاوہ ازیں اس روایت سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی پر ایک ایسی بصیرت افزار روشنی پڑتی ہے جسے کوئی مؤرخ نظر انداز
نہیں کر سکتا اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ روایت ایسے اعلیٰ ترین مقام پر واقع ہوئی ہے جس میں شک وشبہ
کی گنجائش نہیں سمجھی جاسکتی.اب غور کا مقام ہے کہ یہ کس قدر خطرناک فتنہ تھا جو منافقین کی طرف سے کھڑا
کیا گیا.اس میں صرف ایک پاک دامن اور نہایت درجہ متقی اور پر ہیز گار عورت کی عصمت پر ہی حملہ کرنا
مقصود نہ تھا بلکہ بڑی غرض بالواسطہ مقدس بانی اسلام کی عزت کو برباد کرنا اور اسلامی سوسائٹی پر ایک
خطر ناک زلزلہ وارد کرنا تھی اور منافقین نے اس گندے اور کمینے پروپیگنڈا کو اس طرح پر چر چا دیا تھا کہ بعض
سادہ لوح مگر سچے مسلمان بھی ان کے دام تزویر میں الجھ کر ٹھو کر کھا گئے.ان لوگوں میں حسان بن ثابت
شاعر اور حمنہ بنت جحش ہمشیرہ زینب بنت جحش اور مسطح بن اثاثہ کا نام خاص طور پر مذکور ہوا ہے.مگر حضرت
عائشہ کا یہ کمال اخلاق ہے کہ انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان کی طرف سے اپنے دل میں کوئی
رنجش نہیں رکھی.چنانچہ روایت آتی ہے کہ اس کے بعد جب کبھی حسان بن ثابت حضرت عائشہ سے ملنے
آتے تھے تو وہ بڑی کشادہ پیشانی سے ان سے ملتی تھیں.ایک دفعہ وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر
ہوئے تو اس وقت ایک مسلمان مسروق نامی بھی وہاں موجود تھے.مسروق نے حیران ہو کر کہا کہ ” ہیں !
آپ حسان کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دیتی ہیں! حضرت عائشہ نے جواب دیا ” جانے دو
بیچارہ آنکھوں کی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے.یہ کیا کم عذاب ہے.پھر میں اس بات کو نہیں بھول سکتی کہ
حسان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اور کفار کے خلاف شعر کہا کرتا تھا.چنانچہ حسان کو اجازت
دی گئی اور وہ اندر آ کر بیٹھ گئے.اور حضرت عائشہ کی تعریف میں یہ شعر کہا.حَصَانٌ رَزَانٌ مَاتُزَنُ بِرِيبَةٍ
وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْعَوَافِلِ
یعنی وہ ایک پاک دامن عفیفہ خاتون ہیں اور صاحب عقل و دانش ہیں اور ان کی پوزیشن شک وشبہ
ا بخاری کتاب المغازی باب حدیث الا فک نیز کتاب التفسیر تفسیر سورۃ نور بخاری حدیث افک
Page 655
۶۴۰
کے مقام سے بالا ہے.اور وہ غافل بے گناہ عورتوں کا گوشت نہیں کھا تیں یعنی ان پر اتہام نہیں لگاتیں
اور نہ ان کی غیبت فرماتی ہیں.“
حضرت عائشہ نے یہ شعر سنا تو فرمایا.وَلكِنُ اَنتَ.اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لَسْتَ
كَذَالِکَ یعنی ” تمہارا اپنا کیا حال ہے تم تو اس خوبی کے مالک ثابت نہیں ہوئے.یعنی تم نے تو مجھے بے
گناہ کے خلاف الزام لگانے میں شمولیت اختیار کی.میور صاحب کی عربی دانی یا تعصب کی مثال ملاحظہ
ہو کہ اس شعر کے بالکل غلط اور خلاف قواعد عربی معنی کر کے لکھتے ہیں کہ حسان نے عائشہ کے نازک بدن کی
تعریف کی تھی جس پر عائشہ نے شوخی کے ساتھ ان کی فربہی پر طعن کیا.بریں عقل و دانش بباید گریست !
میور صاحب نے اس قصہ کے بیان کرنے میں اور بھی فاش غلطیاں کی ہیں.مثلاً لکھتے ہیں کہ صفوان
اور عائشہ راستے میں فوج کو نہ پہنچ سکے اور پھر بعد میں برسر منظر عام مدینہ میں داخل ہوئے.حالانکہ یہ
بات بالکل غلط اور قطعاً بے بنیاد ہے کیونکہ حدیث و تاریخ سے متفقہ طور پر ثابت ہے کہ صفوان اور حضرت
عائشہ چند گھنٹے کے بعد راستہ میں ہی اسلامی لشکر میں آملے تھے.مگر اس قدر غنیمت ہے کہ اصل اتہام
کے متعلق میر صاحب نے حضرت عائشہ کی معصومیت کا اعتراف کیا ہے.چنانچہ لکھتے ہیں.عائشہ کی قبل اور بعد کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ اتہام سے بری تھیں.66
گو عقلی اور نفلی طور پر یہ اتہام بالکل غلط اور جھوٹ قرار پاتا ہے کیونکہ سوائے اس سراسر اتفاقی واقعہ
کے کہ حضرت عائشہ شکر اسلامی کے پیچھے رہ گئی تھیں اور پھر صفوان کے ساتھ بعد میں پہنچیں اتہام
لگانے والوں کے ہاتھ میں قطعاً کوئی بات نہیں تھی یعنی نہ کوئی شہادت تھی اور نہ ہی کوئی اور ثبوت تھا اور ظاہر
ہے کہ جب تک کوئی الزام ثابت نہ ہو اسے ہرگز سچا نہیں سمجھا جاسکتا خصوصاً ایسے لوگوں کے متعلق جن کی
زندگی ان کی طہارت نفس پر شاہد ہو.مگر مسلمانوں کے مزید اطمینان کے لئے اور نیز اس غرض سے کہ
آئندہ کے لئے ایسے معاملات میں ایک اصولی قاعدہ مقرر ہو جاوے خدائی وحی نازل ہوئی جس نے نہ
صرف اس اتہام کو سراسر جھوٹا قرار دے کر حضرت عائشہ اور صفوان بن معطل کی بریت ظاہر فرمائی بلکہ
آئندہ کے لئے اس قسم کے واقعات کے متعلق ایک ایسا اصولی قانون دنیا کے سامنے پیش فرمایا جس پر
بخاری تفسیر سورة نور
میور صفحه ۲۹۴
بخاری حدیث الا فک و طبری و ابن ہشام
۳ میور صفحه ۲۹۰
۵ میور صفحه ۲۹۴
Page 656
۶۴۱
افراد کی عزت و آبرو اور سوسائٹی کے امن و امان اور ملت کے اخلاق کی حفاظت کا بڑی حد تک دار و مدار
ہے.اس قانون کی بنا ان اصول پر ہے کہ :
اول ہر انسان کے متعلق اصل قیاس عصمت و عفت کا ہونا چاہئے یعنی یہ کہ ہر انسان عفیف سمجھا جانا
چاہئے جب تک اس کی عصمت و عفت کے خلاف کوئی یقینی اور قطعی ثبوت موجود نہ ہو.دوسرے یہ کہ انسان کی عزت و آبرو ایک نہایت ہی قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت دنیا کی تمام دوسری
چیزوں سے زیادہ ضروری ہے.تیسرے یہ کہ فحشاء کا چر چاندی کے رعب کو مٹاتا اور سوسائٹی کے اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے اس لئے
اس کا سد باب ہونا ضروری ہے.چوتھے یہ کہ جہاں یہ نہایت ضروری ہے کہ زنا کا مجرم عبرتناک سزا پائے وہاں یہ بھی نہایت ضروری
ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والا بغیر سخت سزا کے نہ چھوڑا جاوے.ان اصول کے ماتحت قرآن شریف مندرجہ ذیل قانون پیش فرماتا ہے:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ اِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ليَشْهَدُ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمِنِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَأُولَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ )
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.یعنی جو شخص کسی دوسرے پر زنا کا الزام لگائے اس کا فرض ہے کہ اس الزام کے ثبوت
میں کم از کم چار معتبر چشم دید گواہ پیش کرے.اگر وہ ایسے گواہ پیش کر دے تو جرم ثابت سمجھا
جاوے اور مجرم کو ایک سوڈڑوں کی سزا دی جاوے اور اس سزا میں ہرگز کوئی نرمی اور رعایت
نہ کی جاوے اور نیز یہ سزا علی الاعلان پبلک کے سامنے دی جاوے تا کہ دوسروں کے لئے
موجب عبرت ہو لیکن اگر الزام لگانے والا اپنے الزام کو مذکورہ بالاطریق پر ثابت نہ
کر سکے تو ملزم کو بے گناہ سمجھا جاوے اور الزام لگانے والے کو جھوٹا الزام لگانے کی سزا میں
انٹی ڈڑوں کی سزا دی جاوے اور آئندہ جب تک ایسے لوگ اپنی اصلاح نہ کریں کسی معاملہ
: سورۃ نور : ۳ تا ۶
Page 657
۶۴۲
میں ان کی شہادت قبول نہ کی جاوے.“
اس آیت کریمہ میں جو سزا زانی کی مقرر کی گئی ہے اس کا استحقاق تو ظاہر ہی ہے اور اس کے متعلق
کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.البتہ جھوٹا الزام لگانے والے کی سزا کا سوال بعض سادہ مزاج انسانوں
کے لئے قابل اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایسی سخت سزا کیوں تجویز کی گئی ہے.سو اس کی حقیقت یہ ہے کہ
دراصل اس معاملہ میں کسی پر جھوٹا اتہام باندھنا ایک نہایت خطرناک اور ضرررسان فعل ہے کیونکہ اس میں
ایک بے گناہ انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز پر ناجائز اور مفتریانہ حملہ ہونے کے علاوہ سوسائٹی کے
اخلاق پر بھی ایک نہایت گندہ اثر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس طرح پر کہ جب اس قسم کی باتوں کے متعلق کسی
سوسائٹی میں آزادانہ چرچا ہوگا تو لازماً زنا کی بدی کا رعب طبائع سے کم ہونے لگے گا اور کمزور طبیعتیں
گندے خیالات کی طرف مائل ہونے لگیں گی اور ملک اور قوم کی اخلاقی فضا زہر آلود ہو جائے گی.پس ضروری تھا کہ اس معاملہ میں جھوٹے الزام لگانے والوں کے واسطے سخت سزا تجویز کی جاتی تاکہ
سوائے بچے آدمی کے کسی کو اس قسم کے الزام لگانے کی جرات نہ پیدا ہوا اور صرف وہی شخص اتہام لگانے
میں آگے آسکے جو واقعی اپنے پاس یقینی ثبوت رکھتا ہو اور اگر کسی کو یہ شبہ گزرے کہ اسلام نے اس معاملہ
میں ثبوت کے متعلق نا واجب سختی سے کام لیا ہے یعنی چار چشم دید گواہوں کو ضروری قرار دے کر ثبوت
کے قیام کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے تو یہ ایک عامیانہ شبہ ہوگا.جب ہر جرم کے ثبوت کے لئے کوئی نہ کوئی
تسلی بخش طریق ثبوت مقرر کیا جانا ضروری ہوتا ہے تو پھر ایک ایسے الزام کے ثبوت کے لئے جس میں
انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز پر حملہ ہو اور جس کے غلط اور جھوٹے استعمال سے سوسائٹی کے امن وامان
اور قوم کے اخلاق و عادات پر ایک سخت خطرناک اور گندہ اثر پڑتا ہوا ایک نہایت زبر دست اور یقینی طریق
ثبوت کیوں نہ مقرر کیا جا تا خصوصاً جبکہ دنیا بھر میں قانون سازی کا یہ ایک مسلم اصول ہے کہ کسی بے گناہ
کے مجرم قرار پانے سے یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ ایک مجرم بے گناہ سمجھا جاوے.اس جگہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ زنا کے مجرم کے لئے بدنی سزا کیوں تجویز کی گئی ہے.سواس کا
جواب یہ ہے کہ اسلام میں سزاؤں کا فلسفہ اس اصول پر مبنی ہے کہ جس نوعیت کا جرم ہو اسی نوعیت کی سزا
ہونی چاہئے تا کہ سزا کی بڑی غرض جو اصلاح ہے پوری ہو سکے.پس چونکہ زنا کا جرم خاص طور پر بدنی
شہوات کے غلبہ اور ان کے بے قابو ہو جانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لئے ضروری تھا کہ اس جرم میں
بدنی سزا مقرر کی جاتی تاکہ بدنی طاقتوں کو صدمہ پہنچنے سے مجرم کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہوا اور
Page 658
۶۴۳
الزام لگانے والوں کے لئے بدنی سزا اس لئے رکھی گئی ہے کہ جوشخص دوسرے پر زنا کا جھوٹا الزام لگا کر
اسے ذلیل کرنا چاہتا اور بدنی سزا دلوانا چاہتا ہے اسے اسی قسم کی سزا دے کر وہ جو ایک بے گناہ کو دلوانا
چاہتا تھا ہوش میں لایا جاوے اور نیز تا اس قسم کی سزا دوسروں کے لئے موجب عبرت ہوا اور ملک وقوم
گندے اثرات سے محفوظ رہیں.واللہ اعلم
جویریہ بنت حارث کی شادی قبیلہ بنومصطلق کے جو قیدی گرفتار ہوئے تھے ان میں اس قبیلہ کے
سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی بڑ بھی تھی جو مسافع بن صفوان کے
عقد میں تھی جو غز وہ مریسیع میں مارا گیا تھا.ان قیدیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب دستور
مسلمان سپاہیوں میں تقسیم فرما دیا تھا اور اس تقسیم کی رو سے بڑہ بنت حارث ایک انصاری صحابی ثابت بن
قیس کی سپردگی میں دی گئی تھی..برہ نے آزادی حاصل کرنے کے لئے ثابت بن قیس کے ساتھ مکا تبت
کے طریق پر یہ سمجھوتہ کیا کہ وہ اگر اسے اس قدر رقم فدیہ کے طور پر ادا کر دے تو آزاد کبھی جاوے.اس
سمجھوتہ کے بعد بڑہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارے حالات سنائے.اور یہ جتلا کر کہ میں بنو مصطلق کے سردار کی لڑکی ہوں فدیہ کی رقم کی ادائیگی میں آپ کی اعانت چاہی.اس
کی کہانی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور غالبا یہ خیال کر کے کہ چونکہ وہ ایک مشہور قبیلہ
کے سردار کی لڑکی ہے شاید اس کے تعلق سے اس قبیلہ میں تبلیغی آسانیاں پیدا ہو جا ئیں آپ نے ارادہ
فرمایا کہ اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی فرمالیں.چنانچہ آپ نے اسے خود اپنی طرف سے پیغام دیا
اور اس کی طرف سے رضامندی کا اظہار ہونے پر آپ نے اپنے پاس سے اس کے فدیہ کی رقم ادا فرما کر
اس کے ساتھ شادی کر لی.صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کے آقا نے بنو مصطلق کی رئیس زادی کو
شرف ازدواجی عطا فر مایا ہے تو انہوں نے اس بات کو خلاف شانِ نبوی سمجھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے سسرال والوں کو اپنے ہاتھ میں قید رکھیں اور اس طرح ایک سوگھرانے یعنی سینکڑوں قیدی بلافد یہ یک لخت
آزاد کر دئیے گئے.اسی وجہ سے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ جوہر یہ ( آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بڑہ کا نام بدل کر جو یر یہ کر دیا تھا اپنی قوم کے لئے نہایت مبارک وجود ثابت ہوئی ہے.اس رشتہ
: اصابه وزرقانی حالات جویریہ
: ابن ہشام وابوداود کتاب العتق
: ابن سعد وابوداؤد کتاب العتق
ابن ہشام حالات غزوہ مصطلق وابوداؤ د کتاب العتق وزرقانی جلد ۳ حالات جویریہ
Page 659
۶۴۴
اور اس احسان کا یہ نتیجہ ہوا کہ بنو مصطلق کے لوگ بہت جلد اسلام کی تعلیم سے متاثر ہوکر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو گئے.برة کا نام بدلنے میں یہ حکمت تھی کہ چونکہ بڑۃ کے معنی نیکی کے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند
نہیں فرماتے تھے کہ کبھی جب برق گھر میں نہ ہوں اور کوئی شخص ان کے متعلق یہ دریافت کرے کہ آیا برة
گھر میں ہیں یا نہیں تو اسے یہ جواب ملے کہ برق گھر میں نہیں ہے جس کے بظاہر یہ معنی ہیں کہ گویا نیکی اور
برکت گھر سے
اٹھ گئی ہے.یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے مگر اس سے اس محبت پر بہت روشنی پڑتی ہے جو
نیکی اور طہارت کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب میں رکھتے تھے.حضرت جویریہ کی شادی کے متعلق ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب ان کے والد انہیں چھڑانے
کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے فیض صحبت سے مسلمان
ہو گئے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملنے پر انہوں نے خود برضا و رغبت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دی ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جویریہ کے والد
حارث نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ میں سردار قوم ہوں میری لڑکی
اس طرح قید میں نہیں رکھی جاسکتی.آپ نے فرمایا کہ جویریہ سے پوچھا جاوے اگر وہ آزاد ہو کر واپس جانا
چاہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اگر ہمارے پاس ٹھہرنا چاہے تو ہمارے پاس ٹھہرے.جو یہ یہ
سے پوچھا گیا تو اس نے مسلمان ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کیا جس پر
آپ نے اسے آزادکر کے اس کے ساتھ شادی فرمالی.کے
عزل یعنی برتھ کنٹرول کی اجازت اس غزوہ یعنی غزوہ بنو مصطلق میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے دریافت کرنے پر عزل یعنی
برتھ کنٹرول کے متعلق فرمایا کہ میں اسے ناجائز نہیں کہتا.یعنی بالفاظ دیگر آپ نے اس بات کو جائز
قرار دیا کہ کوئی شخص کسی ضرورت و مصلحت سے کوئی ایسی تدبیر اختیار کرے کہ اس کی بیوی کو اس کی
مجامعت سے حمل نہ ٹھہرے.ابن سعد جلد ۸ حالات جویریہ
اصابه جلده احالات جویریہ
: زرقانی جلد ۳ حالات جویریہ نیز ابن ہشام جلد ۳ حالات ازواج
بخاری حالات غزوہ بنو مصطلق و موطا امام مالک و ترندی باب ماجاء في العزل
Page 660
۶۴۵
اس فتوی کی رو سے ایک مسلمان کے لئے جائز ہوگا کہ اپنی بیوی کی صحت و تندرستی یا اولاد کی
صحت و تندرستی یا کسی اور جائز مصلحت سے برتھ کنٹرول کے اصول پر عمل پیرا ہو مگر جیسا کہ ایک قرآنی
آیت سے استدلال ہوتا ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ غربت اور مالی تنگی کے اندیشہ سے
برتھ کنٹرول کا طریق اختیار کیا جاوے.اور نہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بیوی کی رضامندی کے
بغیر یہ طریق اختیار کیا جاوے.یہ مسئلہ گو اس زمانہ کے لحاظ سے ایک بالکل غیراہم سا مسئلہ تھا مگر موجودہ
زمانہ میں اس نے خاصی اہمیت اور دلچسپی اختیار کر لی ہے.ل : سورۃ بنی اسرائیل :۳۲
ابن ماجہ بحوالہ مشکوۃ کتاب النکاح باب المباشرت فصل ثالث
Page 661
۶۴۶
مدینہ کا محاصرہ اور مسلمانوں کی نازک حالت
کفار کی نامرادی.حقیقت معجزه
جنگ احزاب یعنی غزوہ خندق اب ہم تاریخ اسلامی کے اس حصہ میں داخل ہوتے
ہیں جبکہ اسلام کے خلاف قبائل عرب کی دشمنی نہ
شوال ۵ ہجری مطابق فروری و مارچ ۶۲۷ء صرف انتہا کو پہنچ گئی بلکہ انہوں نے ایک متحدہ تدبیر
کے ماتحت اپنی طاقتوں کو جمع کر کے اسلام کی بیخ کنی کا تہیہ کرلیا مگر قدرت الہی کا ایسا تصرف ہوا کہ ان
کے اس اتحاد میں ہی ناکامی کا تخم پیدا ہو گیا اور ابھی یہ عمارت پوری طرح کھڑی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ
اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو کر گرنی شروع ہو گئیں.تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مکہ کے قریش اور نجد کے
قبائل غطفان وسلیم گو پہلے سے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہور ہے تھے اور آئے دن مدینہ کے
خلاف حملہ آوری کی فکر میں رہتے تھے مگر ابھی تک انہوں نے اپنی طاقتوں کو اسلام کے خلاف ایک
میدان میں مجتمع نہیں کیا تھا لیکن جب یہود کے قبیلہ بنو نضیر کے لوگ اپنی غداری اور فتنہ انگیزی کی وجہ
سے مدینہ سے جلا وطن کئے گئے تو ان کے رؤساء نے اس شریفانہ بلکہ محسنانہ سلوک کو فراموش کرتے
ہوئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا آپس میں یہ تجویز کی کہ عرب
کی تمام منتشر طاقتوں کو
ایک جا جمع کر کے اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جاوے اور چونکہ یہودی لوگ بڑے ہوشیار و
چالاک تھے اور اس قسم کے سازشی کاموں میں خوب مہارت رکھتے تھے اس لئے ان کی مفسدانہ کوششیں
بار آور ہوئیں اور قبائل عرب ایک جان ہو کر مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکل آئے.یہودی رؤساء میں سے سلام بن ابی الحقیق.حی بن اخطب اور کنانہ بن الربیع نے اس اشتعال انگیزی
ابن سعد
Page 662
۶۴۷
میں خاص طور پر حصہ لیا.چنانچہ ان فتنہ پردازوں نے اپنے نئے وطن خیبر سے نکل کر حجاز اور نجد کے قبائل
کا دورہ کیا اور سب سے پہلے مکہ میں پہنچ کر قریش کو اپنے ساتھ گانٹھا.اور رؤساء قریش کو خوش کرنے کے
لئے اس بات تک کے کہنے سے دریغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے دین سے تمہارا دین (شرک و بت پرستی)
اچھا ہے." اس کے بعد انہوں نے نجد میں جا کر قبیلہ غطفان کو اپنے ساتھ ملایا " اور اس قبیلہ کی
شاخہائے فرارہ اور مرہ اور اشجع وغیرہ کو اپنے ساتھ نکلنے کے لئے تیار کر لیا.پھر قریش اور غطفان کی
انگیخت سے قبائل بنو سلیم اور بنو اسد بھی اس مخالف اسلام اتحاد کی کڑی میں منسلک ہو گئے..اور دوسری
طرف یہود نے اپنے حلیف قبیلہ بنو سعد کو پیغام بھیج کر اپنی اعانت کے لئے کھڑا کر لیا.اس زبر دست
اتحاد کے علاوہ قریش نے اپنے گردو نواح کے قبائل میں سے بھی بہت سے لوگوں کو جو ان کے توابع میں
سے تھے اپنے ساتھ ملالیا اور پھر پوری تیاری کے بعد صحرائے عرب کے یہ خونخوار قبائل مسلمانوں کو
ملیا میٹ کرنے کے ارادے سے ایک سیل عظیم کی طرح مدینہ پر امڈ آئے.اور یہ عزم کیا کہ جب تک
اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹا نہیں لیں گے واپس نہیں لوٹیں گے.کفار کے اس عظیم الشان لشکر کا اندازہ دس ہزار نفوس سے لے کر پندرہ ہزار بلکہ بعض روایات کی
رو سے چوبیس ہزار تک لگایا گیا ہے.اگر دس ہزار کے اندازے کو ہی صحیح تسلیم کیا جاوے تو پھر بھی اس
زمانہ کے لحاظ سے یہ تعداد اتنی بڑی تھی کہ غالبا اس سے پہلے عرب کے قبائلی جنگوں میں اتنی بڑی تعداد
کبھی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئی ہوگی.جنگ کی کمان کا انتظام یہ تھا کہ سارے لشکر کا قائد اعظم یعنی
سپہ سالا را بوسفیان بن حرب تھا.جو سپہ سالار ہونے کے علاوہ اپنے قبیلہ قریش کا امیر العسکر بھی تھا.قبائل غطفان کی مجموعی کمان عیینہ بن حصن فزاری کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ماتحت ہر قبیلہ کا الگ الگ
کمانڈر تھا.بنوسلیم کا کمانڈر سفیان بن عبد شمس تھا اور بنو اسدا اپنے رئیس طلیحہ بن خویلد کی کمان میں
تھے.سامان خوردونوش اور سامان جنگ بھی ہر طرح کافی وشافی تھا.اس طرح یہ لشکر شوال ۵ ہجری
ابن ہشام
: ابن سعد وابن ہشام
: ابن ہشام وابن سعد
ابن ہشام
ے خمیس
ابن سعد
ا زرقانی
فتح الباری بحوالہ سیرۃ النبی جلد اصفحه ۳۸۶
۱۲ : ابن سعد
۱۳ ابن ہشام
سے ابن ہشام
: ابن سعد و تمیس
ابن ہشام وابن سعد
۱۴: ابن سعد
Page 663
۶۴۸
مطابق فروری و مارچ ۶۲۷ء میں مدینہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا.لے
اتنے بڑے لشکر کی نقل و حرکت کا مخفی رکھنا کفار کے لئے مشکل تھا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا جاسوسی کا انتظام بھی نہایت پختہ تھا.چنانچہ ابھی قریش کا لشکر مکہ سے نکلا ہی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچ گئی.جس پر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے اس کے متعلق مشورہ فرمایا.اس مشورہ میں
ایران کے ایک مخلص صحابی سلمان فارسی بھی شریک تھے جن کے اسلام لانے کا ذکر اوپر گزر چکا ہے.چونکہ
سلمان فارسی عجمی طریق جنگ سے واقف تھے انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ مدینہ کے غیر محفوظ حصہ کے
سامنے ایک لمبی اور گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جاوے.خندق کا خیال عربوں کے لئے بالکل
نیا تھا، لیکن یہ معلوم کر کے کہ یہ طریق جنگ دیار عجم میں عام طور پر کامیابی کے ساتھ رائج ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو منظور فرمایا.اور چونکہ مدینہ کا شہر تین طرف سے ایک حد تک محفوظ تھا یعنی
مکانات کی مسلسل دیواروں اور گھنے درختوں اور چٹانوں کے سلسلے کی وجہ سے یہ اطراف لشکر کفار کے
اچانک حملہ سے محفوظ تھیں اور صرف شامی طرف ایسی تھی جہاں دشمن ہجوم کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوسکتا تھا
اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر محفوظ طرف میں خندق کے کھودے جانے کا حکم دیا.کے اور
آپ نے خود اپنی نگرانی میں موقع پر نشان لگا کر تقسیم کار کے اصول کے ماتحت خندق کو دس دس ہاتھ یعنی
پندرہ پندرہ فٹ کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑہ دس دس صحابیوں کے سپرد فرما دیا.ان پارٹیوں کی تقسیم میں یہ خوشگوا را ختلاف رونما ہوا کہ سلمان فارسی کس گروہ میں شمار ہوں.آیا وہ مہاجر سمجھے جائیں یا بوجہ اس کے کہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں آئے ہوئے تھے انصار
میں شمار ہوں.بوجہ اس کے کہ سلمان اس طریق جنگ کے محرک تھے اور ویسے بھی ایک مستعد اور
باوجود بوڑھے ہونے کے مضبوط آدمی تھے ہر فرقہ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا.آخر یہ اختلاف
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور آپ نے فریقین کے دعاوی سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا
کہ سلمان دونوں میں سے نہیں ہے بلکہ سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ یعنی ” سلمان میرے اہل بیت میں شمار
کئے جائیں.‘ ۵ اس وقت سے سلمان کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
گھر کے آدمی سمجھے جانے لگے.ابن ہشام
طبری وابن سعد و روض الانف
تاریخ خمیس و زرقانی
بیہقی بحوالہ فتح الباری جلدے صفحہ ۳۰۵
د: طبری
Page 664
۶۴۹
الغرض خندق کی تجویز پختہ ہونے کے بعد صحابہ کی جماعت مزدوروں کے لباس میں ملبوس ہو کر میدان
کارزار میں نکل آئی.کھدائی کا کام کوئی آسان کام نہیں تھا اور پھر یہ موسم بھی سردی کا تھا جس کی وجہ سے ان
ایام میں صحابہ نے سخت تکالیف اٹھا ئیں اور چونکہ دوسرے کاروبار بالکل بند ہو گئے تھے اس لئے وہ لوگ
جن کا کام روز کی روٹی روز کمانا تھا اور صحابہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی ان کو تو ان دنوں میں بھوک
اور فاقہ کشی کی مصیبت بھی برداشت کرنی پڑی اور چونکہ صحابہ کے پاس نوکر اور غلام بھی نہ تھے اس لئے
سب صحابہ کو خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھالے
جو دس دس کی ٹولیاں مقرر ہوئی تھیں انہوں نے اپنے کام کی اندرونی تقسیم اس طرح کی تھی کہ کچھ
آدمی کھدائی کرتے تھے اور کچھ کھدی ہوئی مٹی اور پتھروں کو ٹوکریوں میں بھر بھر کر اپنے کندھوں پر لاد کر
باہر پھینکتے جاتے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیشتر حصہ اپنے وقت کا خندق کے پاس گزارتے
تھے اور بسا اوقات خود بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کھدائی اور مٹی کی ڈھلائی کا کام کرتے تھے اور ان کی
طبیعتوں میں شگفتگی قائم رکھنے کے لئے بعض اوقات آپ کام کرتے ہوئے شعر پڑھنے لگ جاتے تھے
جس پر صحابہ بھی آپ کے ساتھ سُر ملا کر وہی شعر دہراتے تھے.چنانچہ روایات میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا اس موقع پر مندرجہ ذیل شعر پڑھنا خصوصیت کے ساتھ مذکور ہوا ہے.اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرُ لِلا نُصَارِ وَالْمُهَاجِرَة
یعنی اے ہمارے مولا! اصل زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے.پس تو اپنے فضل سے ایسا سامان
کر کہ انصار و مہاجرین کو آخرت کی زندگی میں تیری بخشش اور عطا نصیب ہو جاوے.“
اس شعر کے جواب میں بعض اوقات صحابہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ ؎
=
نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَدًا عَلَى الْجِهَادِ مَابَقِيْنَا اَبَدًا
یعنی ”ہم وہ ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ عہد کیا ہے کہ ہم ہمیشہ جب
تک کہ ہماری جان میں جان ہے خدا کے رستے میں جہاد کرتے رہیں گے.“
اور کبھی آپ اور صحابہ عبداللہ بن رواحہ انصاری کے یہ اشعار پڑھتے تھے
بخاری حالات غزوہ احزاب
بخاری حالات خندق
بخاری حالات غزوہ خندق
Page 665
اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَانُزِلَنْ سَكِيْنَةٌ عَلَيْنَا وَثَبِّتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لَا قَيْنَا
إِنَّ الْالَى قَدْ بَغَوُا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةٌ أَبَيْنَا
یعنی اے ہمارے مولا ! اگر تیر افضل نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی اور ہم صدقہ
و خیرات کرنے اور تیری عبادت کرنے کے قابل نہ بنتے.پس اے خدا! جب تو نے ہمیں اس
حد تک پہنچایا ہے تو اب اس مصیبت کے وقت میں ہمارے دلوں کو سکینت عطا کر اور اگر
دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ.تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ظلم
اور تعدی کے رنگ میں حملہ آور ہورہے ہیں اور ان کی نیت ہمیں اپنے دین سے بے دین کرنا
ہے مگر اے ہمارے خدا! تیرے فضل سے ہمارا یہ حال ہے کہ جب وہ ہمیں بے دین کرنے
کے لئے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کی تدبیر کو دور سے ہی ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کے
فتنہ میں پڑنے سے انکار کرتے ہیں.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مصرعہ پر پہنچتے تھے تو اپنی آواز کو بلند فرما دیتے تھے.ایک
صحابی کی روایت ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا کہ
آپ کا جسم مبارک مٹی اٹھانے کی وجہ سے گردوغبار سے بالکل ڈھکا ہوا تھا.بھوک اور فاقہ کشی کا یہ عالم
تھا کہ اور صحابیوں کا تو کیا کہنا ہے خود سرور کائنات پر کئی کئی وقت کا فاقہ آجا تا تھا اور آپ اس کی تکلیف
سے بچنے کے لئے پیٹ پر پتھر باندھے پھرتے تھے.سے
اسی تنگی اور شدت کی حالت میں خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ سے ایک پتھر نکلا جو کسی طرح ٹوٹنے
میں نہ آتا تھا اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ تین دن کے مسلسل فاقہ سے سخت نڈھال ہورہے تھے.آخر تنگ
آکر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک پتھر ہے جو ٹوٹنے میں
بخاری حالات خندق
بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ احزاب و کتاب الجہاد
ے عربوں میں قاعدہ تھا کہ بھوک کی سخت شدت کے وقت جبکہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا پیٹ پر حجر یعنی پتھر باندھ لیتے
تھے جس سے جسم ضعف کی وجہ سے جھکنے سے محفوظ رہتا تھا اور غالباً اسی رسم سے اردو میں بھی یہ محاورہ قائم ہو گیا ہے کہ فلاں
شخص پیٹ پر پتھر باندھے پھرتا ہے.یا یہ بھی ممکن ہے کہ حجر سے مراد کمر کا پکا ہو کیونکہ عربی میں جبر کپڑے کو بھی کہتے ہیں
دیکھو مجمع البحار.واللہ اعلم
Page 666
۶۵۱
نہیں آتا.اس وقت آپ کا بھی یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا مگر آپ فوراوہاں
تشریف لے گئے اور ایک کدال لے کر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس پتھر پر ماری.لوہے کے لگنے سے پتھر
میں سے ایک شعلہ نکلا جس پر آپ نے زور کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مجھے مملکت شام کی
کنجیاں دی گئی ہیں اور خدا کی قسم اس وقت شام کے سرخ محلات میری آنکھوں کے سامنے ہیں.اس ضرب
سے وہ پتھر کسی قدر شکستہ ہو گیا.دوسری دفعہ آپ نے پھر اللہ کا نام لے کر کدال چلائی اور پھر ایک شعلہ نکلا
جس پر آپ نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اس دفعہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں اور مدائن کے سفید
محلات مجھے نظر آرہے ہیں.اس دفعہ پھر کسی قدر زیادہ شکستہ ہو گیا.تیسری دفعہ آپ نے پھر کدال ماری
جس کے نتیجہ میں پھر ایک شعلہ نکلا اور آپ نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اب مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی
ہیں اور خدا کی قسم صنعاء کے دروازے مجھے اس وقت دکھائے جارہے ہیں.اس دفعہ وہ پتھر بالکل شکستہ
ہوکر اپنی جگہ سے گر گیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر بلند آواز
سے تکبیر کہی اور پھر بعد میں صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ نے یہ کشوف بیان فرمائے.اور مسلمان اس
عارضی روک کو دور کر کے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نظارے عالم
کشف سے تعلق رکھتے تھے.گو یا اس تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کی آئندہ فتوحات اور
فراخیوں کے مناظر دکھا کر صحابہ میں امید و شگفتگی کی روح پیدا فرمائی مگر بظاہر حالات یہ وقت ایسا تنگی اور
تکلیف کا وقت تھا کہ منافقین مدینہ نے ان وعدوں کو سن کر مسلمانوں پر پھبتیاں اڑائیں کہ گھر سے باہر
قدم رکھنے کی طاقت نہیں اور قیصر و کسریٰ کی مملکتوں کے خواب دیکھے جارہے ہیں.تے مگر خدا کے علم میں یہ
ساری نعمتیں مسلمانوں کے لئے مقدر ہو چکی تھیں.چنانچہ یہ وعدے اپنے اپنے وقت پر یعنی کچھ تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ کے خلفاء کے زمانہ میں پورے ہوکر
مسلمانوں کے از دیا دایمان وامتنان کا باعث ہوئے.اسی موقع پر ایک مخلص صحابی جابر بن عبد اللہ نے آپ کے چہرہ پر بھوک کی وجہ سے کمزوری اور
نقاہت کے آثار دیکھ کر آپ سے اپنے گھر جانے کی اجازت لی.اور گھر آکر اپنی بیوی سے کہا کہ
لے بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ خندق
: احمد و نسائی و طبرائی و بیہقی بحوالہ فتح الباری جلد کے صفحیم ۳۰۵،۳۰ نیز زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۱۰،۱۰۹
ابن ہشام
Page 667
۶۵۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت کی وجہ سے سخت تکلیف معلوم ہوتی ہے.کیا تمہارے پاس
کھانے کے لئے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں کچھ جو کا آتا ہے اور ایک بکری ہے.جابر کہتے ہیں کہ اس پر میں
نے بکری کو ذبح کیا اور آٹے کو گوندھا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا تیار کرو.میں رسول اللہ کی
خدمت میں جا کر عرض کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں.میری بیوی نے کہا دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا.کھانا
تھوڑا ہے رسول اللہ کے ساتھ زیادہ لوگ نہ آئیں.جابر کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے آہستگی کے ساتھ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! میرے پاس کچھ گوشت اور جو کا آٹا ہے جن کے
پکانے کے لئے میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں آپ اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلیں اور کھانا
تناول فرما ئیں.آپ نے فرمایا.کھانا کتنا ہے میں نے عرض کیا کہ اس اس قدر ہے.آپ نے فرمایا بہت
ہے.پھر آپ نے اپنے اردگرد نگاہ ڈال کر بلند آواز سے فرمایا اے انصار و مہاجرین کی جماعت! چلو جابر
نے ہماری دعوت کی ہے چل کر کھانا کھالو.اس آواز پر کوئی ایک ہزار فاقہ مست صحابی آپ کے ساتھ
ہو لئے.آپ نے جابر سے فرمایا کہ تم جلدی جلدی جاؤ اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آلوں
ہنڈیا کو چولہے پر سے نہ اتارے اور نہ ہی روٹیاں پکانا شروع کرے.جابر نے جلدی سے جا کر اپنی بیوی
کو اطلاع دی اور وہ بیچاری سخت گھبرائی کہ کھانا تو صرف چند آدمیوں کے اندازہ کا ہے اور آرہے ہیں اتنے
لوگ ! اب کیا ہوگا.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی بڑے اطمینان کے ساتھ ہنڈیا اور
آٹے کے برتن پر دعا فرمائی اور پھر فرمایا اب روٹیاں پکانا شروع کر دو.اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ
کھانا تقسیم کرنا شروع فرما دیا.جابر روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے کہ اسی کھانے سے سب لوگ سیر ہو کر اٹھ گئے اور ا بھی ہماری ہنڈیا اسی طرح اہل رہی تھی اور
آٹا اسی طرح پک رہا تھا.معجزہ کی حقیقت یہ واقعہ بخاری کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب حدیث اور کتب تاریخ میں بیان ہوا
ہے اور چونکہ اصول شہادت وروایت کے لحاظ سے یہ واقعہ بالکل صحیح قرار پاتا ہے
اور اس کے تمام راوی ہر طرح قابل اعتماد ہیں اور ابتدائی راوی اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہیں اس لئے
باوجود اس کے کہ اس روایت میں ایک ایسی بات بیان کی گئی ہے جو عام اور معروف قانون قدرت کے
خلاف ہے، میں نے اسے اپنے اس تاریخی بیان میں درج کرنے میں تامل محسوس نہیں کیا.دراصل اس قسم
ل : بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ احزاب و فتح الباری ۷ صفحه ۳۰۴ تا ۳۰۷
Page 668
۶۵۳
کے واقعات کے متعلق عقلاً اور شرعاً اصل قابل تحقیق باتیں چار ہوتی ہیں :
اول یہ کہ واقعہ کا وقوع معتبر اور چشم دید شہادت سے پوری طرح ثابت ہو یعنی یہ کہ اس کے وقوع
کے متعلق اصول شہادت کے لحاظ سے کوئی معقول شبہ نہ کیا جا سکے لے
دوسرے یہ کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہئے جو خدا تعالیٰ کی کسی بیان کر دہ سنت یا
اس کے کسی غیر مشروط وعدے یا کسی مسلمہ صفت کے خلاف ہو.کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ خدا کی
طرف سے ایسے معجزات و خوارق ظاہر ہوں جن کی وجہ سے کسی نہ کسی رنگ میں خود اسی کی ذات پر
اعتراض وارد ہوتا ہو.تیسرے یہ کہ اس کی نوعیت ایسی ہونی چاہئے کہ اس میں کسی نہ کسی جہت سے انسانی علم اور انسانی
قدرت سے کوئی بالا چیز پائی جاتی ہوتا کہ وہ اس بات کی علامت سمجھی جا سکے کہ اس کا منبع انسانی دل و دماغ
نہیں ہے بلکہ کوئی بالا ہستی ہے.چوتھے یہ کہ اس میں ایک حد تک اخفاء کا رنگ بھی پایا جاتا ہو.یعنی ایسی صورت نہ ہو جو خدا تعالیٰ کی
ذات وصفات اور اس کے مرسلین کی صداقت وغیرہ کے متعلق گویا مشاہدہ کا مرتبہ پیدا کر دے اور حقیقت
ایسی کھل جائے کہ اس میں امکانی طور پر بھی کسی قسم کے شک پیدا کرنے کی گنجائش نہ رہے جیسا کہ
مثلاً سورج کے وجود کے متعلق کسی انسان کے لئے شک کی گنجائش نہیں ہے.کیونکہ اگر ایسے معجزات ظاہر
ہوں تو اس سے ایمان کی غرض فوت ہو جاتی ہے اور ایمان لانا کار ثواب نہیں رہتا ہے
آخر الذکر امر کے متعلق یہ بات بھی یادرکھنی چاہئے کہ معجزات میں جو اخفا کا پردہ رکھا جاتا ہے اس کے
مختلف مدارج ہوتے ہیں یعنی بعض معجزات میں اخفاء کا پردہ زیادہ ہوتا ہے اور بعض میں نسبتا کم ہوتا ہے
اور اس جہت سے معجزات کی قسمیں موٹے طور پر دو سمجھی جاسکتی ہیں.اوّل وہ معجزات جو غیر مومنین کی ہدایت اور ان پر اتمام حجت کرنے کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں.ان میں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی سنت سے پتہ لگتا ہے اور عقل بھی یہی چاہتی ہے اخفا کا پردہ زیادہ رکھا جاتا
: سورۃ حجرات: ۷.سورۃ تحریم : ۴.سورۃ توبہ : ۱۲۰
ہے : سورۃ بنی اسرائیل : ۷۸.سورۃ احزاب : ۶۳.سورۃ روم: ۷.۷.سورة هود : ۶۲ تا ۶۶.سورۃ حشر : ۱۹ تا ۲۵.۳ : سورۃ قمن :۱۲٬۱۱.سورۃ شوری ۱ تا ۲۰
سورۃ اعراف: ۱۸۱
۴ سورة بقره : ۴.سورۃ حدید: ۲۶.سورۃ یونس: ۸۸، ۹۱ تا ۹۳
Page 669
ہے.یعنی اس قسم کے معجزات میں صرف اس قدر روشنی دکھائی جاتی ہے جو محض ایک دھندلے طریق پر
راستہ دکھا سکے.چنانچہ متقین نے لکھا ہے کہ عام طور پر معجزہ کی مثال ایسی ہے جیسے چاندنی رات کی روشنی
جس کے کچھ حصہ میں بادل بھی ہو.اس قسم کی روشنی پیدا ہونے پر وہ لوگ جن کی آنکھوں کی بینائی کا نور باقی
ہوتا ہے راستہ دیکھ لیتے ہیں مگر وہ لوگ جن کی آنکھوں میں بینائی کا نور مر چکا ہوتا ہے یا شب کور ہوتے
ہیں یا جنہوں نے تعصبات کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھی ہوتی ہے وہ راستہ کی طرف ہدایت نہیں پاتے.لے
اس لئے باوجود اس قسم کے معجزات دکھائے جانے کے سعید اور شقی میں امتیاز قائم رہتا ہے اور ایمان کا
ثواب ضائع نہیں جاتا.دوم وہ معجزات جو مومنین کے لئے دکھائے جاتے ہیں.جو قسم اول کے معجزات
سے روشنی پا کر صحیح راستہ اختیار کر چکے ہوتے ہیں.ان لوگوں کے لئے طبعا اخفا کے پردے کم کر دئیے
جاتے ہیں اور بسا اوقات انہیں ایسے معجزات دکھائے جاتے ہیں جو حقیقی مشاہدہ کا رنگ تو نہیں رکھتے مگر
ان میں اخفا کا پردہ صورت اول کی نسبت بہت کم ہوتا ہے اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ تا یہ لوگ ایمان
و عرفان کے اعلیٰ مراتب کی طرف ترقی کر سکیں.چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کی
ابتداء غیب سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان حسب استعداد صالحیت اور شہیدیت اور
صدیقیت اور نبوت کے مراتب کی طرف ترقی کرتا جاتا ہے.اور لازم جوں جوں ایمان کا مرتبہ ترقی کرتا
ہے معجزات کی نوعیت بھی ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہے اور اخفاء کے پردے کم ہوتے جاتے ہیں.چنانچہ شہید
تو کہتے ہی اسے ہیں جس کے لئے اخفا کے پردے کم کر دیئے گئے ہوں.اب اگر اس اصولی قاعدہ کے ماتحت اوپر والے واقعہ کے متعلق غور کیا جاوے تو کوئی حقیقی اعتراض
وارد نہیں ہوتا کیونکہ نہ صرف یہ کہ اصول شہادت و روایت کے لحاظ سے اس واقعہ کا وقوع پوری طرح
ثابت ہے اور کسی معقول شبہ کی گنجائش نہیں کی جاسکتی بلکہ وہ خدا کی کسی بیان کردہ سنت یا کسی غیر مشروط
وعدے یا کسی مسلمہ صفت کے بھی خلاف نہیں ہے اور پھر اگر ایک طرف اس میں انسانی طاقت سے بالا
قدرت کا مظاہرہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف گو اس وجہ سے کہ یہ واقعہ صرف مومنین کے سامنے وقوع میں
آیا اور انہی کے ایمان کی زیادتی اس کی غرض وغایت تھی اس میں اخفا کا پردہ کم نظر آتا ہے.مگر بہر حال
وہ ایسے مشاہدہ کا مرتبہ پیدا نہیں کرتا جس میں امکانی طور پر بھی کوئی جہت تاویل کی باقی نہ رہے اور
نصف النہار کے سورج کی طرح حقیقت ظاہر ہو جاوے.کیونکہ مثلاً امکانی طور پر ایسا ہوسکتا ہے کہ کسی
ل : براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحه ۳۳
سورۃ فاتحہ : ۷،۶ نیز سورۃ نساء : ۷۰
Page 670
مخفی تغیر کے ماتحت انسانی معدہ پر کسی وقت ایسا غیر معمولی تصرف ہو کہ وہ اپنے معمول کی نسبت بہت تھوڑی
غذا کھانے سے ہی شکم سیری محسوس کرنے لگے.وغیر ذالک
اب رہا یہ امر کہ اس حدیث میں ایک ایسی بات بیان کی گئی ہے جو ہمارے عام مشاہدہ اور معروف
قانون قدرت کے خلاف ہے.سو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو قانون قدرت کی حد بندی ایک نہایت ہی
مشکل چیز ہے بلکہ حقیقت نا ممکن ہے اور یقینی اور قطعی طور پر یہ قرار دے دینا کہ یہ یہ بات قانون قدرت میں
شامل ہے اور یہ یہ بات شامل نہیں ہے ایک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے جس کی کوئی عقل مند شخص جرات نہیں
کر سکتا اور حق یہ ہے کہ جب ایک بات عملاً وقوع پذیر ہو جاوے اور سمجھدار اور صادق القول لوگوں کی ایک
جماعت اس کی شاہد ہوتو پھر وہی بات قانون قدرت کا حصہ سمجھی جانی چاہئے اور ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ
گو عام طور پر قانون قدرت اس اس رنگ میں ظاہر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کسی ایسے مخفی تغیر کی وجہ سے جسے
ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے اس میں اس اس رنگ میں استثنا بھی ہو جاتی ہے.علاوہ ازیں ہمیں یہ بھی یا درکھنا
چاہئے کہ چونکہ معجزات کی بڑی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ تا خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کے مرسلین کی
صداقت کے متعلق ایسے نشانات قائم کئے جائیں جن سے سعید لوگ حق کی طرف یقینی راہ پانے اور پھر
اس راہ پر ترقی کرنے میں آسانی محسوس کریں اور دنیا کی تاریکیوں میں ان کے لئے روشنی کی چمک پیدا
ہو جاوے.اس لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں معجزات میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جو انسانی
قدرت و علم سے بالا کبھی جاسکے.پس جہاں ایک طرف ایمان کی غرض وغایت کا یہ تقاضا ہے کہ کم از کم ابتدا
میں مشاہدہ کا رنگ نہ پیدا ہو اور اخفاء کا پردہ قائم رہے وہاں دوسری طرف زندہ ایمان پیدا کرنے
کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اخفاء کے پردوں کو ایک حد تک کم کر کے
کبھی کبھی حقیقت کی جھلک بھی دکھا دی
جاوے اور انہی دو نقطوں کی وسطی حالت کے مظاہرہ کا نام معجزہ ہے جسے اس کی حقیقت کوملحوظ رکھتے
ہوئے قرآنی محاورہ میں آیت یعنی نشان اور علامت کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے.دراصل خدا کی ہستی ایسی وراء الوراء ہے (اور اپنے مقام کے لحاظ سے وہ وراء الوراء ہی ہونی
چاہئے ) کہ اس پر ایمان لانے اور اسے پہچاننے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے محض ذہنی اور قیاسی
استدلالات ہرگز انسان کے دل میں وہ یقین پیدا نہیں کر سکتے جو زندہ ایمان کی بنیاد بننے کے لئے ضروری
ہے جس کے نتیجہ میں خدا کا وجود ایک محض خیالی فلسفے کا حصہ نہیں رہتا بلکہ اسی طرح محسوس و مشہور ہو جاتا
ہے جیسا کہ اس دنیا کی چیز میں محسوس و مشہور ہیں گو نوعیت میں اس سے بہت مختلف اور انسان خدا کے ساتھ
Page 671
ایک ذاتی تعلق پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو اس کی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے.پس ضروری تھا کہ خدا
کی طرف سے ایسے سامان مہیا کئے جاتے جو انسان کے دل میں اس قسم کا ایمان پیدا کر سکیں اور انہیں
سامانوں کا ایک حصہ آیات و معجزات و خوارق ہیں جو خدا کے انبیاء وصلحاء کے ذریعہ ہر زمانہ میں ظاہر ہوتے
رہے ہیں اور جس کی مثالیں ہر قوم وملت میں پائی جاتی ہیں.اس جگہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ عام معروف قانون قدرت
کے خلاف کوئی امر ظا ہر ہو.تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ ایک امر واقع ہے کہ اس قسم کے امور ظاہر
ہوتے رہتے ہیں اور کثیر التعداد عقل مند معتبر لوگوں کی شہادت اسے سچا ثابت کرتی ہے اور یہ شہادت
ہر زمانہ اور ہر قوم میں پائی جاتی ہے تو کوئی عقل مند اس قسم کے واقعات کی سچائی کے متعلق شبہ نہیں
کر سکتا.علاوہ ازیں کم از کم ان لوگوں کے لئے جو فی الجملہ اس دنیا کا کوئی خالق مانتے ہیں اور اس بات
کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود اپنے آپ سے نہیں ہے بلکہ ایک بالا ہستی کی قدرت خلق سے عالم
وجود میں آئی ہے اور یہ کہ وہی بالا ہستی اب اس کا رخانہ عالم کو چلا رہی ہے اور تمام خواص الاشیاء اور
قوانین قدرت اسی وراء الوراء ہستی کے حکم کے ماتحت جاری ہیں اس بات کے سمجھنے میں کوئی روک نہیں
ہوسکتی کہ وہی بالا و قادر ہستی اپنے عام قانون میں کسی خاص وقت میں کسی خاص مصلحت کے ماتحت کوئی
تبدیلی یا استثناء بھی کر سکتی ہے.چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ O یعنی اللہ اپنے حکم پر بھی غالب اور حکمران ہے مگر اکثر لوگ
سمجھتے نہیں.یعنی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے دنیا کا قانون بنا دیا تو بس اب ہمارے ہاتھ بندھ گئے بلکہ ہم اپنے
قانون پر بھی حکمران اور غالب ہیں اور جب مناسب سمجھیں اس میں
تبدیلی یا استثنا کر سکتے ہیں.اسی لئے
محققین نے لکھا ہے کہ دراصل خدا کی طرف سے دنیا میں دو تقدیر میں جاری ہیں ایک تو یہی عام معروف
قانون قدرت ہے جسے تقدیر عام کہتے ہیں اور جس کے ماتحت یہ کارخانہ عالم اپنے عام حالات میں جاری
نظر آتا ہے.دوسرے وہ خاص قانون ہے جو خاص اوقات میں خاص مصالح کے لئے جاری ہوتا ہے
جسے تقدیر خاص کہتے ہیں جو آیات و معجزات کے طریق پر رونما ہوتی ہے اور جس کے ذریعہ خدا کا وجود تقدیر
عام کی نسبت بہت زیادہ روشن صورت میں انسان کے سامنے آجاتا ہے.مگر یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ آیات و معجزات کا ظہور صرف تقدیر خاص کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے اور
: سورۃ یوسف : ۲۲
تقدیر الهی صفحه ۱۲۴ تا ۱۴۳
Page 672
تقدیر عام کے ذریعہ سے نہیں ہوتا.کیونکہ بسا اوقات آیات کا ظہور اس رنگ میں بھی ہوتا ہے کہ چند
تقادیر عام غیر معمولی طور پر ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں یا چند تقادیر عام ایک غیر معمولی ترتیب کے ساتھ رونما
ہوتی ہیں اور اس غیر معمولی اجتماع یا غیر معمولی ترتیب کے نتیجہ میں ایک رنگ آیت و معجزہ کا پیدا ہو جاتا
ہے.مگر یہ ایک وسیع اور نازک مضمون ہے جس کے تفصیلی بیان کی اس جگہ گنجائش نہیں.خلاصہ کلام یہ کہ آیات و معجزات کا سلسلہ برحق ہے اور ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور جابر بن عبداللہ کی
دعوت کا واقعہ اسی مقدس سلسلہ کی ایک کڑی ہے اور چونکہ یہ معجزہ صرف مومنین کو دکھایا گیا تھا اس لئے
سنت اللہ کے ماتحت اس میں اخفا کا پر وہ نسبتا کم تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ سے
پتہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ ایک منفرد واقعہ نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی میں اس قسم کے بہت سے واقعات پائے
جاتے ہیں جو صحیح روایات سے ثابت ہیں اور انشاء اللہ ان میں سے بعض آگے چل کر اپنے موقع پر بیان
کئے جائیں گے مگر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جیسا کہ معجزات کی غرض و غایت سے ظاہر ہے اور جیسا کہ قرآن
شریف کی متعدد آیات سے بھی ثبوت ملتا ہے معجزات میں رسول کی ذات صرف ایک ذریعہ اور واسطہ
ہوتی ہے اور اصل متصرف ہستی خدا کی ہوتی ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک رسول جب اور جس طرح چاہے
اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھاوے بلکہ معجزات کا معاملہ صرف خدا کی مرضی اور مصلحت پر موقوف ہوتا
ہے.وہ جب اور جس طرح چاہتا ہے اپنے کسی رسول کے ذریعہ سے معجزات کا اظہار فرماتا ہے اور گو رسول
کی توجہ اور دعا معجزات کی جاذب اور محرک ضرور ہوتی ہے مگر حکم خدا کی طرف سے آتا ہے اور اس کی
مخفی قدرت رسول کے اندر سے ہو کر اپنا کام کرتی ہے اور جب خدا کا حکم نہ ہو تو رسول کی ذاتی طاقت
کوئی معجزہ پیدا نہیں کر سکتی اور ظاہر ہے کہ خدا کا حکم بھی ہوتا ہے جب کوئی حقیقی ضرورت اور حقیقی مصلحت
اس کی متقاضی ہوتی ہے.اس جگہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ چونکہ معجزات کے متعلق عموماً جھوٹی اور بناوٹی روایات یا مبالغہ
آمیز باتیں بھی کثرت کے ساتھ مشہور ہو جایا کرتی ہیں.اس لئے اس معاملہ میں روایات کے قبول کرنے
میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہئے اور صرف ان روایات کو قبول کرنا چاہئے جو اصول روایت و درایت
کے مطابق صحیح ثابت ہوں اور ان اصولی شرائط کے مطابق پوری اتریں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں یعنی
اصول شہادت کے لحاظ سے وہ قابل اعتماد ہوں وہ خدا کی کسی سنت یا وعدے یا صفت کے خلاف
نہ ہوں.ان میں انسانی علم اور انسانی قدرت سے کوئی بالا چیز پائی جاتی ہو اور ان میں اخفا کا پردہ اس قدر کم
Page 673
۶۵۸
نہ ہو کہ جو ایمان بالغیب کے اصول کے خلاف سمجھا جاسکے ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط اور بناوٹی قصے صحیح تاریخ
کا حصہ قرار پا کر حقیقت کو بالکل مستور کردیں گے اور دنیا میں معجزات وخوارق کا ایک غلط مفہوم قائم
ہو جائے گا جو بجائے ہدایت کا باعث ہونے کے ضلالت و گمراہی کا موجب بن جائے گا.اس مختصر اور ضمنی
نوٹ کے بعد ہم اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں.غزوہ خندق کے بقیہ حالات
کم و بیش ہیں ایام یا ایک روایت کی رو سے چھ شبانہ روزے کی
مسلسل محنت سے یہ طویل خندق تکمیل کو پہنچی.اور اس غیر معمولی
محنت و مشقت نے صحابہ کو بالکل نڈھال کر دیا.مگر ادھر یہ کام اختتام کو پہنچا اور ادھر یہود اور مشرکین عرب کا
لا ولشکر اپنی تعداد اور طاقت کے نشہ میں مخمور افق مدینہ میں نمودار ہو گیا.سب سے پہلے ابوسفیان نے اُحد کی
پہاڑی کی طرف رخ کیا مگر اس جگہ کو ویران و سنسان پا کر وہ مدینہ کی اس سمت کو بڑھا جو شہر پر حملہ کرنے
کے لئے موزوں تھی مگر اس کے سامنے اب خندق کھودی گئی تھی.جب کفار کا لشکر اس جگہ پہنچا تو خندق کو
اپنے رستہ میں حائل پا کر سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور اس بات پر مجبور ہوئے کہ خندق کے پار کھلے
میدان میں ڈیرے ڈال دیں.دوسری طرف لشکر کفار کی آمد آمد کی خبر پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی
تین ہزار مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکلے اور خندق کے پاس پہنچ کر شہر اور خندق کے درمیان سلع
پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھتے ہوئے ڈیرے ڈال دئے.اور چونکہ خندق زیادہ فراخ نہیں تھی اور بعض
حصے یقیناً ایسے تھے کہ مضبوط اور ہوشیار سوار انہیں پھاند کر شہر کی طرف آ سکتے تھے.اور پھر مدینہ کے وہ
اطراف جہاں خندق نہیں تھی اور صرف مکانات اور باغات اور بے ترتیب چٹانوں کی روک تھی ان کی
حفاظت بھی ضروری تھی تا کہ دشمن اس طرف سے مکانوں کو نقصان پہنچا کر یا کسی اور حکمت سے تھوڑے
تھوڑے آدمیوں کی لائنوں میں ہو کر شہر پر حملہ آور نہ ہو جاوے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو مختلف دستوں میں منقسم کر کے خندق کے مختلف حصوں پر اور مدینہ کی دوسری اطراف میں مناسب
جگہوں پر پہرے کی چوکیاں مقرر فرما دیں اور تاکید فرمائی کہ دن ہو یا رات کسی وقت میں یہ پہرہ ست یا
غافل نہ ہونے پائے کے دوسری طرف جب کفار نے یہ دیکھا کہ بوجہ خندق کی روک کے کھلے میدان کی
با قاعدہ لڑائی یا شہر پر عام دھاوے کا حملہ ناممکن ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی محاصرہ کے رنگ میں مدینہ کا
موسی بن عقبہ بروایت زرقانی جلد ۲ صفحہ ۱۱۰
: ابن ہشام
ابن سعد
ابن سعد وزرقانی
Page 674
۶۵۹
گھیرا ڈال لیا اور خندق کے کمزور حصوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع تلاش کرنے لگ گئے.اس کے علاوہ ابوسفیان نے یہ چال چلی کہ قبیلہ بنو نضیر کے یہودی رئیس حیی بن اخطب کو یہ ہدایت
دی کہ وہ رات کی تاریکی کے پردے میں بنو قریظہ کے قلعہ کی طرف جاوے اور ان کے رئیس کعب بن اسد
کے ساتھ مل کر بنو قریظہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے یا چنانچہ حی بن اخطب موقع لگا کر کعب کے
مکان پر پہنچا.شروع شروع میں تو کعب نے اس کی بات سننے سے انکار کیا اور کہا کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم )
کے ساتھ ہمارے عہد و پیمان ہیں اور محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے ہمیشہ اپنے عہد و پیمان کو وفاداری
کے ساتھ نبھایا ہے اس لئے میں اس سے غداری نہیں کر سکتا.مگر حی نے اسے ایسے سبز باغ دکھائے
اور اسلام کی عنقریب تباہی کا ایسا یقین دلایا اور اپنے اس عہد کو کہ جب تک ہم اسلام کو مٹا نہ لیں گے
مدینہ سے واپس نہیں جائیں گے اس شد ومد سے بیان کیا کہ بالآخر وہ راضی ہو گیا.اور اس طرح
بنو قریظہ کی طاقت کا وزن بھی اس پلڑے کے وزن میں آکر شامل ہو گیا جو پہلے سے ہی بہت جھکا ہوا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی اس خطرناک غداری کا علم ہوا تو آپ نے پہلے تو دو تین دفعہ
خفیہ خفیہ زبیر بن العوام کو دریافت حالات کے لئے بھیجا.اور پھر باضابطہ طور پر قبیلہ اوس وخزرج کے
رئیس سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ اور بعض دوسرے با اثر صحابہ کو ایک وفد کے طور پر بنوقریظہ کی طرف
روانہ فرمایا اور ان کو یہ تاکید فرمائی کہ اگر کوئی تشویشناک خبر ہو تو واپس آکر اس کا برملا اظہار نہ کریں بلکہ
اشارہ کنایہ سے کام لیں تاکہ لوگوں میں تشویش نہ پیدا ہو.جب یہ لوگ بنو قریظہ کے مساکن میں پہنچے اور
ان کے رئیس کعب بن اسد کے پاس گئے تو وہ بد بخت ان کو نہایت مغرورانہ انداز سے ملا.اور سعدین کی
طرف سے معاہدہ کا ذکر ہونے پر وہ اور اس کے قبیلہ کے لوگ بگڑ کر بولے کہ ” جاؤ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )
اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے.یہ الفاظ سن کر صحابہ کا یہ وفد وہاں سے اٹھ کر چلا آیا اور سعد
بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مناسب طریق پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے اطلاع دی ہے.اس وقت مدینہ کا مطلع ظاہری اسباب کے لحاظ سے سخت تاریک و تار تھا.شہر کے چاروں طرف ہزارہا
خونخوار دشمن ڈیرہ ڈالے پڑے تھے جو ہر وقت اس تاک میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو مسلمانوں پر حملہ آور
ابن سعد
ابن ہشام
بخاری حالات غزوہ خندق نیز زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۱۹
ابن ہشام
Page 675
۶۶۰
ہو کر ان کو ملیا میٹ کر دیں.شہر میں مسلمانوں کے پہلو میں غدار بنو قریظہ تھے جن کے سینکڑوں مسلح
نوجوان اپنی ذات میں ایک جری لشکر سے کم نہ تھے اور جو جس وقت چاہتے یا موقع پاتے عقب کی
طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے.اور مسلمان خواتین اور بچے جو شہر میں تھے وہ تو گویا
ہر وقت ان کا شکار ہی تھے.اس صورت حال نے جس کی حقیقت کسی سمجھ دار شخص پر مخفی نہیں رہ سکتی تھی
کمزور مسلمانوں میں سخت پریشانی اور سراسیمگی پیدا کردی اور منافق طبع لوگ تو برملا کہنے لگے کہ
مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُوْلُةَ إِلَّا غُرُورًا یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا اوراس کے رسول کے وعدے
مسلمانوں کی فتح و کامرانی کے متعلق یونہی جھوٹے ہی تھے.بعض منافقین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہو ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ ! شہر میں ہمارے مکانات بالکل غیر محفوظ
ہیں آپ اجازت دیں تو ہم اپنے گھروں میں ٹھہر کر ان کی حفاظت کریں.جس کے جواب میں خدائی
وحی نازل ہوئی کہ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ تُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًان یعنی ” یہ غلط ہے کہ ان لوگوں کو اپنے
گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا خیال ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ میدان کارزار سے بھاگنے کی راہ ڈھونڈ
رہے ہیں.مگر یہی وقت مخلص مسلمانوں کے ایمان کے اظہار کا تھا.چنانچہ قرآن فرماتا ہے
وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ
"
دو
وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمانی ” جب مومنوں نے کفار کے اس لا ولشکر کو دیکھا تو انہوں نے
کہا کہ یہ تو سب کچھ خدا اور اس کے رسول کے وعدوں کے مطابق ہے اور خدا اور رسول ضرور بچے
ہیں.پس اس حملہ سے بھی ان کے ایمان و تسلیم میں زیادتی ہی ہوئی مگر موقع کی نزاکت اور حالات کے
خطرناک پہلو کا سب کو یکساں احساس تھا.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ جَاءُ وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ
وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُوْنَا
هُنَالِكَ ابْتِلَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَ الَّا شَدِيدًا CO یعنی یاد کرو جبکہ کفار کا لشکر تمہارے اوپر اور
تمہارے نیچے کی طرف سے ہجوم کر کے تم پر آ گیا.جبکہ گھبراہٹ میں تمہاری آنکھیں پتھرانے لگیں اور کلیجے
منہ کو آنے لگے اور تم لوگ اپنے اپنے رنگ میں یعنی کوئی کسی رنگ میں اور کوئی کسی رنگ میں ) خدا کے
متعلق مختلف خیالات میں پڑ گئے.وہ وقت واقعی مومنوں کے لئے ایک سخت امتحان کا وقت تھا اور
: سورۃ احزاب: ۱۳
: سورۃ احزاب :
۱۲،۱۱:
ے : سورۃ احزاب: ۱۴
: سورۃ احزاب: ۲۳
Page 676
۶۶۱
مسلمانوں پر ایک نہایت شدید زلزلہ وارد ہوا تھا.“
ایسے خطر ناک وقت میں مسلمانوں کی قلیل جمعیت جن میں بعض کمز ور طبیعت لوگ اور بعض منافق بھی
شامل تھے کیا مقابلہ کرسکتی تھی.ان کے پاس تو اتنے آدمی بھی نہ تھے کہ کمزور مواقع پر خاطر خواہ پہرے کا
انتظام کر سکیں.چنانچہ دن رات کی سخت ڈیوٹی نے مسلمانوں کو چور کر رکھا تھا.دوسری طرف بنو قریظہ کی
غداری کی وجہ سے شہر کی گلی کوچوں کے پہرے کو زیادہ مضبوط کرنا بھی ضروری تھا تا کہ مستورات اور بچے
محفوظ رہ سکیں.کفار کے سپاہی مسلمانوں کو ہر رنگ میں پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے.کبھی وہ کسی
کمزور جگہ پر یورش کر کے جمع ہو جاتے اور مسلمان اس کی حفاظت کے لئے وہاں اکٹھے ہونے لگتے جس پر
وہ فور أرخ پلٹ کر کسی دوسرے موقع پر زور ڈال دیتے اور مسلمان بیچارے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچتے کبھی
وہ ایک ہی وقت میں دو دو تین تین جگہوں پر دھاوا کر کے پہنچتے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی جمعیت منتشر
ہو کر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی اور بعض اوقات حالات بہت نازک صورت اختیار کر لیتے اور قریب ہوتا کہ
کسی کمزور موقعے سے فائدہ اٹھا کر لشکر کفار حدود شہر کے اندر داخل ہو جاوے.ان دھاووں کا مقابلہ
مسلمانوں کی طرف سے عموماً تیروں کے ذریعہ کیا جاتا تھا مگر بعض اوقات کفار کے سپاہی یہ طریق اختیار
کرتے کہ ایک دستہ تو مسلمانوں پر تیروں کی باڑ مار مار کر انہیں پیچھے رکھتا اور دوسرا دستہ یورش کر کے خندق
کے کسی کمزور حصہ پر دھاوا کر کے آجاتا اور اسے کود کر عبور کرنا چاہتا.یہ طریق جنگ صبح سے لے کر شام
تک بلکہ بعض اوقات رات کے حصوں میں بھی جاری رہتا تھا.چنانچہ سرولیم میور اس جنگ کے دودن کے
واقعات کو مندرجہ ذیل الفاظ میں سپرد قلم کرتے ہیں :
مسلمانوں کے پہرے کی ہوشیاری اتحادیوں کی فوج کے حملوں کو روکے ہوئے
تھی.اتحادی فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ممکن ہو تو خندق پر دھاوا کر کے اسے عبور کر جائیں اور
اس غرض سے انہوں نے خندق کے ایک کمزور اور تنگ حصہ کو منتخب کر کے اس پر ایک عام دھاوا
کر دیا.چنانچہ ان میں سے بعض جانباز سپاہی عکرمہ بن ابوجہل کی کمان کے ماتحت اپنے
گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے خندق کے اس حصہ پر یورش کر کے آئے اور اپنے تیز گھوڑوں کو
اُڑاتے ہوئے خندق کے اوپر سے کود کر مسلمانوں کے سامنے آگئے.ادھر سے علی اپنے ایک
دستہ کو ساتھ لے کر ان کی طرف لپکے اور اس پارٹی نے بڑی ہوشیاری سے عکرمہ کے دستے کا
ابن سعد و خمیس و زرقانی
Page 677
۶۶۲
چکر کاٹ کر ان کے پیچھے ہٹنے کا راستہ بند کر دیا.اس موقع پر عکرمہ کا ایک جہاں دیدہ سپاہی
عمر و بن عبد ودر اپنی پارٹی سے آگے نکل کر انفرادی جنگ کا طالب ہوا.حضرت
علی فوراً اس کے
مقابلہ میں نکلے اور تھوڑی دیر کے لئے یہ دونوں جنگجو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے
رہے.پھر عمر و اپنے گھوڑے سے اترا اور اس کی کونچیں کاٹ کر اسے نیچے گراد یا اور اس کے بعد
اس عزم کے ساتھ علی کی طرف بڑھا کہ یا تو فتح پائے گا یا مارا جائے گا.پھر دونوں آپس میں
گتھم گتھا ہو گئے اور ان کے قدموں کی گرد نے ان کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا لیکن
ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس گرد کے بادل میں سے اللہ اکبر کی گرج نکلی اور لوگوں نے سمجھ لیا
کہ علی نے عمر د کو مار لیا ہے.اس موقع پر مسلمانوں کی توجہ کو دوسری طرف مصروف پا کر عکرمہ اور
اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر پھر دوسرے پارکود گئے.سوائے نوفل کے جو کودنے کی
کوشش میں گر گیا اور زبیر کے ہاتھ سے مارا گیا.قریش نے عمرو کی لاش حاصل کرنے کے لئے
بہت سا روپیہ مسلمانوں کو دینا چاہا.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کے ساتھ اس تجویز
کو ٹھکرا دیا اور عمرو کی لاش اتحادیوں کے یونہی مفت حوالہ کر دی.اس دن اس کے سوا اور کوئی کارروائی نہیں ہوئی لیکن یہ رات بڑی تیاریوں میں گزری
اور دوسرے دن صبح کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام اتحادی لشکر کو اپنے سامنے صف آرا پایا.اتحادیوں کے ہوشیاری کے حملوں سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو ہر وقت چوکس رہنا پڑتا تھا.کسی وقت تو وہ ایک عام دھاوے کی صورت بنا کر حملہ آور ہونے لگتے اور کسی وقت مختلف
دستوں میں تقسیم ہو کر ایک ہی وقت میں مختلف موقعوں پر زور ڈال دیتے اور پھر ایک جگہ سے
ہٹ کر یکلخت دوسری جگہ پر جا کو دتے اور بالآخر اپنی تمام طاقت جمع کر کے کمزور ترین مقام پر
حملہ آور ہو جاتے اور تیروں کی خطرناک بوچھاڑ کی آڑ میں خندق کو عبور کرنے کی کوشش
کرتے.کئی دفعہ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص جیسے نامور لیڈروں نے شہر پر حملہ آور ہونے
یہ روایت درست نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ نوفل بن عبداللہ کی لاش کے متعلق گزرا تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل
کے لئے آگے بڑھا تھا مگر زبیر بن العوام کے ہاتھ سے خود قتل ہو کر گرا.کفار نے اس کی لاش کے معاوضہ میں دس
ہزار درہم مسلمانوں کو دینا چاہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ لینے سے انکار فرما دیا اور لاش یونہی واپس
فرما دی.دیکھو زرقانی جلد ۲ صفحہ ۱۱۴.
Page 678
۶۶۳
کے لئے اسی طرح زور شور سے دھاوا کیا.اور ایک دفعہ تو خود محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کا خیمہ
بھی خطرہ کی حالت میں ہو گیا تھا لیکن مسلمانوں کے بہادار نہ مقابلہ اور تیروں کی بارش نے
حملہ آوروں کو پسپا کر دیا.یہ حالت سارا دن جاری رہی اور چونکہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی
فوج تعداد میں ایسی قلیل تھی کہ شہر کی حفاظت کے واسطے بمشکل کافی ہو سکتی تھی اس لئے مسلمانوں
کو یہ سارا دن مسلسل طور پر مصروف رہنا پڑا.بلکہ رات پڑنے پر بھی خالد کے دستے نے اس
خطرہ کو جاری رکھا اور مسلمان اپنی ڈیوٹی سے فارغ نہیں ہو سکے ،لیکن دشمن کو کامیابی نصیب
نہیں ہوئی.یعنی وہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکا کہ کسی بڑی تعداد میں خندق کو عبور کر سکے.اس
جنگ میں مسلمانوں کے پانچ آدمی مارے گئے اور اسی دن سعد بن معاذ رئیس قبیلہ اوس کو
بھی ابن العرقہ کے تیر نے مہلک طور پر کلائی میں زخمی کیا.اس کے مقابلہ میں اتحادیوں کے
صرف تین آدمی قتل ہوئے.اس دن کے مقابلہ کی سختی اور مسلسل مصروفیت کی وجہ سے مسلمان
اپنی نمازیں بھی وقت پر ادا نہیں کر سکے.چنانچہ جب رات کا ایک حصہ گزر چکا اور دشمن کا
بیشتر حصہ آرام کرنے کے لئے اپنے کیمپ کی طرف لوٹ گیا، اس وقت مسلمانوں نے جمع ہو کر
سارے دن کی نمازیں اکٹھی ادا کیں.اور اس وقت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے کفار پر لعنت
66
بھیجتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیں نمازوں سے روکا ہے خدا ان کے پیٹوں اور ان کی قبروں
کو جہنم کی آگ سے بھرے.“ 1
میور صاحب کے اس دلچسپ نوٹ میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس دن مسلمانوں کی ساری
نمازیں وقت پر ادا نہیں ہو سکیں یہ درست نہیں ہے بلکہ جیسا کہ صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے بات
صرف یہ ہوئی تھی کہ چونکہ اس وقت تک صلوٰۃ خوف مشروع نہیں ہوئی تھی اس لئے بوجہ مسلسل خطرے
اور مصروفیت کے صرف ایک نماز یعنی عصر بے وقت ہوگئی تھی جو مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھی گئی.ت اور
بعض روایات کی رو سے صرف ظہر وعصر کی نماز بے وقت ادا ہوئی تھی.سے
علاوہ ازیں حضرت علی اور عمرو بن عبدود کے مقابلہ کے متعلق میور صاحب کا بیان بہت مختصر
لائف آف محمد مصنفه سرولیم میور صفحه ۳۰۱،۳۰۰
صحیح بخاری حالات غزوہ خندق و نیز مسلم وترندی و ابوداؤ دو نسائی بحوالہ زرقانی جلد ۲ صفحہ ۱۲۳،۱۲۲
ے : مؤطا واحمد ونسائی بحوالہ زرقانی
ہے.
Page 679
۶۶۴
تاریخ میں یہ لڑائی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور اس کے بعض حصے نہایت دلچسپ ہیں.دراصل عمر و ایک نہایت نامور شمشیر زن تھا اور اپنی بہادری کی وجہ سے اکیلا ہی ایک ہزار سپاہی کے برابر سمجھا
جاتا تھا.اور چونکہ وہ بدر کے موقع پر خائب و خاسر ہو کر واپس گیا تھا اس لئے اس کا سینہ مسلمانوں کے
خلاف بغض وانتقام کے جذبات سے بھرا ہوا تھا.اس نے میدان میں آتے ہی نہایت مغرورانہ لہجے میں
مبارز طلبی کی بعض صحابہ اس کے مقابلہ سے کتراتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے
حضرت علی اس کے مقابلہ کے لئے آگے نکلے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ان کو عنایت
فرمائی اور ان کے واسطے دعا کی ہے
حضرت علی نے آگے بڑھ کر عمرو سے کہا.میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اگر قریش میں
سے کوئی شخص تم سے دو باتوں کی درخواست کرے گا تو تم ان میں سے ایک بات ضرور مان لو گے.عمرو نے
کہا.ہاں، حضرت علی نے کہا تو پھر میں پہلی بات تم سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو مان کر خدائی انعامات کے وارث بنو عمرو نے کہا یہ نہیں ہوسکتا.حضرت علی نے کہا.اگر یہ
بات منظور نہیں ہے تو پھر آؤ میرے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاؤ.اس پر عمر و ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا میں نہیں
سمجھتا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے یہ الفاظ کہ سکتا ہے.پھر اس نے حضرت علی کا نام ونسب پوچھا اور ان کے
كم
بتانے پر کہنے لگا " بھیجے اتم ابھی بچے ہو.میں تمہارا خون نہیں گرانا چاہتا اپنے بڑوں میں سے کسی کو بھیجو.کے
حضرت علی نے کہا تم میرا خون نہیں گرانا چاہتے مگر مجھے تمہارا خون گرانے میں تامل نہیں ہے.اس پر
عمر و جوش میں اندھا ہو کر اپنے گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی کونچیں کاٹ کر اسے نیچے گراد یا اور پھر ایک
آگ کے شعلہ کی طرح دیوانہ وار حضرت علی کی طرف بڑھا اور اس زور سے حضرت
علی پر تلوار چلائی کہ وہ
ان کی ڈھال کو قلم کرتی ہوئی ان کی پیشانی پر لگی.اور انہیں کسی قدر زخمی کیا مگر ساتھ ہی حضرت علی نے
الله اَكْبَرُ کا نعرہ لگاتے ہوئے ایسا وار کیا کہ وہ اپنے آپ کو بچا تارہ گیا اور حضرت علی کی تلوار سے شانے
پر سے کاٹتی ہوئی نیچے اتر گئی اور عمرو تر پتا ہوا گرا اور جان دے دی.لیکن اس جزوی اور وقتی غلبہ کا عام لڑائی پر کوئی اثر نہیں تھا.اور یہ دن مسلمانوں کے لئے نہایت
خمیس جلد ا صفحه ۵۴۷
: ابن سعد جلد ۲ صفحه ۴۹
کے خمیس جلد اصفحہ ۵۴۷ وزرقانی
: ابن ہشام ۳ : خمیس جلد اصفحه ۵۴۸
ابن ہشام
زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۱۴
ابن ہشام خمیس وزرقانی وابن ہشام
Page 680
تکلیف اور پریشانی اور خطرے کے دن تھے اور جوں جوں یہ محاصرہ لمبا ہوتا جاتا تھا مسلمانوں کی
طاقت مقابلہ لازماً کمزور ہوتی جاتی تھی اور گوان کے دل ایمان واخلاص سے پر تھے مگر جسم جو مادی
قانون اسباب کے ماتحت چلتا ہے مشتعل ہوتا چلا جار ہا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو
دیکھا تو آپ نے انصار کے رؤساء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلا کر انہیں سارے حالات جتلائے اور
مشورہ مانگا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے اور ساتھ ہی اپنی طرف سے یہ ذکر فرمایا کہ اگر تم لوگ
چا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبیلہ غطفان کو مدینہ کے محاصل میں سے کچھ حصہ دینا کر کے اس جنگ کو ٹال دیا
جاوے.سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے یک زبان ہو کر عرض کیا کہ 'یا رسول اللہ ! اگر آپ کو اس بارہ
میں کوئی خدائی وحی ہوئی ہے تو سرتسلیم خم ہے اس صورت میں آپ بے شک خوشی سے اس تجویز کے مطابق
کارروائی فرمائیں.آپ نے فرمایا ”نہیں نہیں مجھے اس معاملہ میں وحی کوئی نہیں ہوئی میں تو صرف آپ
لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے مشورہ کے طریق پر پوچھتا ہوں.سعدین نے جواب دیا کہ پھر ہمارا یہ مشورہ ہے
کہ جب ہم نے شرک کی حالت میں کبھی کسی دشمن کو کچھ نہیں دیا تو اب مسلمان ہو کر کیوں دیں.واللہ ہم انہیں
تلوار کی دھار کے سوا کچھ نہیں دیں گے.چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار ہی کی وجہ سے فکر
تھا جو مدینہ کے اصل باشندہ تھے اور غالبا اس مشورہ میں آپ کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ انصار کی ذہنی
کیفیت کا پتہ لگا ئیں کہ کیا وہ ان مصائب میں پریشان تو نہیں ہیں.اور اگر وہ پریشان ہوں تو ان کی دلجوئی
،،
فرمائیں.اس لئے آپ نے پوری خوشی کے ساتھ ان کے اس مشورہ کو قبول فرمایا اور جنگ جاری رہی.جنگ کے دوران میں مسلسل مصروفیت اور پریشانی کی وجہ سے صحابہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
کئی کئی وقت کا فاقہ بھی ہو جاتا تھا.چنانچہ ایک دن بعض صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقہ کشی کی
شکایت کی اور عرض کیا کہ ہم کئی دن سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے پھرتے ہیں.اس پر آپ نے اپنے شکم
مبارک پر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو دو پتھر باندھے ہوئے تھے.یہ ان فاقہ کشیوں کے ساتھ جنگ کے دوسرے
مصائب نے مل کر مسلمانوں کے لئے نہایت تکلیف دہ حالات پیدا کر ر کھے تھے اور ہر وقت کے خطرے
کے اندیشے کی وجہ سے جو اثر ان کے دل و دماغ اور اعصاب پر پڑتا تھا وہ مزید براں تھا.اور طبعا اس
مصیبت کا سب سے زیادہ بوجھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا.چنانچہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں رہی ہوں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ے ابن ہشام وابن سعد و زرقانی
ترمذی ابواب الزہد
Page 681
کے لئے جس قد رسخت غزوہ خندق تھا ایسا کوئی اور غزوہ نہیں گزرا.اس غزوہ میں آپ کو بے انتہا تکلیف اور
پریشانی برداشت کرنی پڑی اور صحابہ کی جماعت کو بھی سخت مصائب کا سامنا ہوا اور یہ دن بھی سخت سردی اور
مالی تنگی کے دن تھے.لے
دوسری طرف شہر میں مستورات اور بچوں کا یہ حال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عموماً شہر
کے ایک خاص حصہ میں جو ایک گونہ قلعہ کا رنگ رکھتا تھا جمع کروا دیا ہے مگر ان کی خاطر خواہ حفاظت کے لئے
کافی مسلمان فارغ نہیں کئے جاسکتے تھے اور خصوصاً ایسے اوقات میں جبکہ میدان جنگ میں دشمن کے حملوں
کا زیادہ زور ہوتا تھا مسلمان خواتین اور بچے قریب بالکل غیر محفوظ حالت میں رہ جاتے تھے اور ان کی
حفاظت کے لئے صرف ایسے مرد رہ جاتے تھے جو کسی وجہ سے میدان جنگ کے قابل نہ ہوں.چنانچہ کسی
ایسے ہی موقع سے فائدہ اٹھا کر یہودیوں نے شہر کے اس حصہ پر حملہ آور ہو جانے کی تجویز کی جس میں
مستورات اور بچے جمع تھے اور جاسوسی کی غرض سے انہوں نے اپنا ایک آدمی اپنے آگے آگے اس محلہ میں
بھیجا.اس وقت اتفاق سے عورتوں کے قریب صرف ایک صحابی حسان بن ثابت شاعر موجود تھے سے جو دل
کی غیر معمولی کمزوری کی وجہ سے میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھے.عورتوں نے جب اس دشمن
یہودی کو ایسے مشتبہ حالات میں اپنے جائے قیام کے آس پاس چکر لگاتے دیکھا تو صفیہ بنت عبدالمطلب
نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں حسان سے کہا کہ یہ شخص معاند یہودی ہے اور یہاں
جاسوسی اور شرارت کے لئے چکر لگا رہا ہے اسے قتل کر دو تا کہ واپس جا کر وہ کسی فتنہ کا موجب نہ بنے مگر
حسان کو اس کی ہمت نہ ہوئی جس پر حضرت صفیہ نے خود آگے نکل کر اس یہودی کا مقابلہ کیا اور اسے
مار کر گرا دیا.اور پھر انہی کی تجویز سے یہ قرار پایا کہ اس یہودی جاسوس کا سرکاٹ کر قلعہ کی اس سمت میں
گرا دیا جاوے جہاں یہودی جمع تھے تا کہ یہودیوں کو مسلمان عورتوں پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہ پڑے
اور وہ یہ سمجھیں کہ ان کی حفاظت کے لئے اس جگہ کا فی مرد موجود ہیں.چنانچہ یہ تدبیر کارگر ہوئی اور
اس موقع پر یہودی لوگ مرعوب ہو کر واپس چلے گئے.2
یہ وقت مسلمانوں پر ایک سخت مصیبت کا وقت تھا.چنانچہ اس مصیبت کی سختی سے گھبرا کر چند صحابہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! جو صورت حال ہے
: ابن ہشام وابن سعد و خمیس : خمیس وابن ہشام
۵ : الخمیس جلد اصفحه ۵۵۰
ل تاریخ خمیس جلد اصفحه ۵۴۶
ابن ہشام
Page 682
۶۶۷
وہ آپ پر عیاں ہے، ہمارا تو کلیجہ منہ کو آرہا ہے.آپ خدا سے خاص طور پر دعا فرما ئیں کہ وہ اس مصیبت
کو دور فرمائے اور ہمیں بھی کوئی دعا سکھائیں جو ہم اس موقع پر خدا سے مانگیں.آپ نے انہیں تسلی دی اور
فرمایا کہ تم خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ وہ تمہاری کمزوریوں پر پردہ ڈالے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور
تمہاری گھبراہٹ کو دور فرمائے.اور پھر آپ نے خود یہ دعا فرمائی کہ اَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَبِ سَرِيعَ
الْحِسَابِ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْزِمُهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ وَزَلْزِلْهُمْ.اور ایک روایت میں
یوں آتا ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِيْنَ يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِينَ اكْشِفُ
هَمِّي وَغَمِّي وَكَرْبِي فَإِنَّكَ تَرَى مَانَزَلَ بِي وَبِاَصْحَابِی.یعنی اے دنیا میں اپنے احکام
کو جاری کرنے والے خدا! اور اے حساب لینے میں دیر نہ کرنے والے! تو اپنے فضل سے کفار کے ان
احزاب کو پسپا فرما.اے میرے قادر ! تو ضرور ایسا ہی کر اور کفار کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما اور ان کی
طاقت پر زلزلہ وار دکر.اے تکلیف میں مبتلا لوگوں کی آہ و پکار کو سننے والے! اے مضطر لوگوں کی دعاؤں
کو قبول کرنے والے! تو ہمارے غم اور فکر اور بے چینی کو دور فرما کیونکہ جو مجھ پر اور میرے اصحاب پر اس
وقت مصیبت وارد ہے وہ تیرے سامنے ہے.“
حسن اتفاق سے اسی وقت یا اس کے قریب قریب ایک شخص نعیم بن مسعود جو قبائل غطفان کی شاخ
قبیلہ المجمع سے تعلق رکھتا تھا جو اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے مدینہ میں پہنچ گیا.یہ شخص
دل میں مسلمان ہو چکا تھا مگر ابھی تک کفار کو اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں تھی.اس حالت سے فائدہ
اٹھاتے ہوئے اس نے کمال ہوشیاری سے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے کفار میں پھوٹ پیدا ہوگئی ہے
لے مسند احمد بحوالہ زرقانی
ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۵۳،۴۹.اس موقع پر ابن ہشام نے یہ روایت کی ہے کہ نعیم بن مسعود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور پھر خود آپ نے اسے اس ڈیوٹی پر لگایا کہ کسی طرح حسن تدبیر سے کفار کو واپس لوٹا
دے.اگر ایسا ہوا ہو تو اصولاً یہ قابل اعتراض نہیں ہے.مگر اصول روایت کی رو سے یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی
کیونکہ اول تو ابن ہشام نے اس واقعہ کو بغیر سند کے بیان کیا ہے مگر اس کے مقابلہ میں ابن سعد نے اپنی روایت کی سند دی
ہے.( دیکھوا بن سعد جلد ۲ صفحه ۵۳) علاوہ ازیں ابن ہشام والی روایت کو جسے محدث شیرازی نے القاب میں نقل کیا ہے
محققین نے ضعیف قرار دیا ہے.(دیکھو الجامع الصغیر للسیوطی جلد ۲ صفحہ ۲) پس صحیح واقعہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ نعیم نے
بطور خود یہ تدبیر کی تھی.واللہ اعلم
بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ خندق
زرقانی
Page 683
۶۶۸
پہلے نعیم بن مسعود قبیلہ بنو قریظہ کے پاس گیا.اور چونکہ ان کے ساتھ اس کے پرانے تعلقات
تھے وہ ان کے رؤساء سے مل کر کہنے لگا کہ میرے خیال میں تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ بد عہدی کر کے قریش وغطفان کے ساتھ مل گئے ہو.قریش و غطفان تو یہاں مدینہ میں صرف چند
دن کے مہمان ہیں.مگر تم لوگوں نے بہر حال یہاں رہنا ہے کیونکہ تمہارا یہ وطن ہے اور یہاں مسلمانوں کے
ساتھ ہی تمہارا واسطہ پڑنا ہے اور تم یہ یاد رکھو کہ قریش وغیرہ یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا کوئی خیال نہیں
کریں گے اور تمہیں یونہی مسلمانوں کے رحم پر چھوڑ کر چلے جائیں گے.پس تم کم از کم ایسا کرو کہ قریش و
غطفان سے کہو کہ بطور یر غمال کے اپنے کچھ آدمی تمہارے حوالہ کر دیں تا کہ تمہیں اطمینان رہے کہ تمہارے
ساتھ کوئی غداری نہیں ہوگی.رؤساء بنو قریظہ کو نعیم کی یہ بات سمجھ آگئی اور وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ
قریش سے یرغمالوں کا مطالبہ کریں تاکہ بعد میں انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ ہو.اس کے بعد نعیم بن مسعود
قریش کے رؤساء کی طرف گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بنو قریظہ خائف ہیں کہ کہیں تمہارے چلے جانے کے بعد
انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ ہو اس لئے وہ تمہارے اس اتحاد میں متزلزل ہورہے ہیں اور یہ ارادہ کر رہے
ہیں کہ بطور ضمانت کے تم سے چند یر غمالوں کا مطالبہ کریں.مگر تم ان کو ہرگز یر غمال نہ دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ
تم سے غداری کر کے تمہارے پر عمال مسلمانوں کے حوالہ کر دیں وغیرہ وغیرہ.اسی طرح اس نے اپنے قبیلہ
غطفان کے پاس جا کر اسی قسم کی باتیں کیں.اب خدا کی طرف سے اتفاق ایسا ہوا کہ قریش وغطفان
پہلے سے ہی یہ تجویز کر رہے تھے کہ مسلمانوں پر پھر ایک متحدہ حملہ کیا جاوے اور یہ حملہ شہر کے چاروں
اطراف میں ایک ہی وقت میں کیا جاوے تا کہ مسلمان اپنی قلت تعداد کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہ کرسکیں
اور کسی نہ کسی جگہ سے ان کی لائن ٹوٹ کر حملہ آوروں کو راستہ دے دے.اس ارادے کے ماتحت انہوں
نے بنو قریظہ کو کہلا بھیجا کہ محاصرہ لمبا ہورہا ہے اور لوگ تنگ آ رہے ہیں.پس ہم نے یہ تجویز کی ہے کہ
سب قبائل مل کر کل کے دن ایک متحدہ حملہ مسلمانوں پر کریں اس لئے تم بھی کل کے حملہ کے واسطے تیار
ہو جاؤ.بنو قریظہ نے جن کے ساتھ نعیم بن مسعود کی پہلے سے بات ہو چکی تھی یہ جواب دیا کہ کل تو ہمارا
سبت کا دن ہے اس لئے ہم معذور ہیں اور ویسے بھی جب تک آپ لوگ اس ضمانت کے طور پر کہ آپ کی
طرف سے بعد میں ہمارے ساتھ غداری نہیں ہو گی اپنے کچھ آدمی ہمارے حوالے نہ کر دیں ہم اس حملہ میں
شامل نہیں ہو سکتے.جب قریش و غطفان کو بنو قریظہ کا یہ جواب گیا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ
ل : ابن ہشام
Page 684
۶۶۹
واقعی نعیم نے سچ کہا ہے کہ بنو قریظہ ہماری غداری پر تلے ہوئے ہیں.دوسری طرف جب بنو قریظہ کو
قریش و غطفان کا یہ جواب گیا کہ ہم پر شمال نہیں دیتے تم نے مدد کو آنا ہے تو ویسے آؤ.تو بنوقریظہ نے کہا کہ
واقعی نعیم نے ہمیں ٹھیک مشورہ دیا تھا کہ قریش و غطفان کی نیت بخیر نہیں ہے اور اس طرح نعیم کی حسن تدبیر
سے کفار کے کیمپ میں انشقاق و اختلاف کی صورت پیدا ہوگئی ہے
یہ وہ تدبیر ہے جو نعیم نے اختیار کی مگر نعیم کا یہ کمال ہے کہ اس نے ایسے نازک مشن کی ادائیگی میں بھی
حتی الوسع کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالی جو معین طور پر کذب بیانی کے نام سے موسوم کی جاسکے.باقی لطائف الحیل کے طریق پر کوئی تدبیر اختیار کرنا یا کوئی ایسا داؤ چلنا جس سے انسان دشمن کے شر سے
محفوظ ہو سکے سو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے بلکہ جنگی فن کا ایک نہایت مفید حصہ ہے جس سے
ظالم دشمن کو خائب و خاسر کرنے اور بے جا کشت و خون کے سلسلے کو روکنے میں بہت مدد لی جاسکتی ہے.ممکن ہے کہ نعیم بن مسعود کی اس امن پسند کوشش کا نتیجہ ضائع چلا جاتا اور ایک عارضی لغزش و تزلزل
کے بعد کفار میں پھر اتحاد و ثبات کی روح پیدا ہو جاتی مگر خدا کی طرف سے ایسا اتفاق ہوا کہ ان واقعات
کے بعد رات کو ایک نہایت سخت آندھی چلی.جس نے کفار کے وسیع کیمپ میں جو ایک کھلی جگہ میں واقع
تھا ایک خطرناک طوفان بے تمیزی برپا کر دیا.خیمے اکھڑ گئے.قتاتوں کے پردے ٹوٹ ٹوٹ کر اڑ گئے.ہنڈیاں الٹ الٹ کر چولھوں میں گر گئیں.اور ریت اور کنکر کی بارش نے لوگوں کے کانوں اور آنکھوں
اور نتھنوں کو بھر دیا اور پھر سب سے بڑھ کر غضب یہ ہوا کہ وہ قومی آگئیں جو عرب کے قدیم دستور کے
مطابق رات کے وقت نہایت التزام کے ساتھ روشن رکھی جاتی تھیں ادھر اُدھر خس و خاشاک کی طرح اڑ کر
مجھنے لگ گئیں ہے ان مناظر نے کفار کے وہم پرست قلوب کو جو پہلے ہی محاصرہ کے تکلیف دہ طول اور
اتحادیوں کی باہمی بے اعتمادی کے تلخ تجربے سے متزلزل ہورہے تھے ایک ایسا دھکا لگایا کہ پھر وہ سنبھل
نہ سکے اور صبح سے پہلے پہلے مدینہ کا افق لشکر کفار کے گردوغبار سے صاف ہوگیا.چنانچہ ایسا ہوا کہ جب اس آندھی کا زور ہوا تو ابوسفیان نے اپنے آس پاس کے قریشی رؤساء کو بلا کر
کہا کہ ہماری مشکلات بہت بڑھ رہی ہیں اب یہاں زیادہ ٹھہر نا مناسب نہیں ہے.اس لئے بہتر ہے کہ ہم
واپس چلے جائیں اور میں تو بہر حال جاتا ہوں.یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دیا اور پھر
ابن ہشام
: ابن سعد
ابن ہشام وزرقانی
زرقانی جلد ۲ صفحه ۲۲ او نمیس جلد اصفحه ۵۵۲
Page 685
۶۷۰
اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا مگر گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ اونٹ کے پاؤں کھولنے یاد نہ رہے اور سوار ہونے
کے بعد اونٹ کے حرکت نہ کرنے سے یاد آیا کہ اونٹ کے پاؤں ابھی تک نہیں کھولے گئے.اس وقت
عکرمہ بن ابو جہل ابوسفیان کے پاس کھڑا تھا اس نے کسی قدر تلخی سے
کہا کہ ابوسفیان !تم امیر العسکر ہوکر لشکر کو
چھوڑ کر بھاگے جارہے ہو اور تمہیں دوسروں کا خیال تک نہیں ہے.اس پر ابوسفیان شرمندہ ہوا اور اونٹ
سے اتر کر کہنے لگا لو میں ابھی نہیں جاتا مگر تم لوگ جلدی تیاری کرو اور جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل
چلو چنانچہ لوگ جلد جلد تیاری میں لگ گئے اور ابوسفیان تھوڑی دیر کے بعد اپنے اونٹ پر سوار ہوکر
واپس روانہ ہو گیا.اس وقت تک بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو قریش کے اس فرار کا علم تک نہیں تھا.مگر
جب قریش کا کیمپ سرعت کے ساتھ خالی ہونا شروع ہوا تو دوسروں کو بھی اس کی اطلاع ہوئی جس پر
انہوں نے بھی گھبرا کر کوچ کا اعلان کر دیا.اور بنو قریظہ بھی اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے." اور
بنو قریظہ کے ساتھ بنو نضیر کا رئیس حیی بن اخطب بھی ان کے قلعوں میں چلا آیا.اور اس طرح صبح کی
سفیدی نمودار ہونے سے پہلے پہلے سارا میدان خالی ہو گیا اور ایک فوری اور محیر العقول تغیر کے طور پر
مسلمان مفتوح ہوتے ہوتے فاتح بن گئے.اسی رات جبکہ کفار اس طرح خود بخود میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے اردگرد کے صحابہ کو مخاطب فرما کر آواز دی کہ تم میں سے کوئی ہے جواس وقت جائے اور لشکر کفار کا
حال معلوم کرے؟ لیکن صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت سردی کی اس قدر شدت تھی اور پھر خوف اور
تھکان اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتا تھا کہ جواب میں کچھ عرض
کر سکے یا اپنی جگہ سے حرکت کرے.آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر حذیفہ بن یمان
کو بلایا.جس پر وہ سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے اٹھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے
ہو گئے.آپ نے کمال شفقت سے ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی
اور فرمایا تم بالکل ڈرو نہیں اور اطمینان رکھو انشاء اللہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی.بس تم چپکے چپکے کفار
سے ابن ہشام
: سيرة حلبيه
ابن ہشام حالات غزوہ بنو قریظہ
ل ابن ہشام وابن سعد و طبری
: خمیس وزرقانی
مسلم كتاب الجهاد
کے ابن ہشام وطبری
مسلم حالات غزوہ خندق
زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۱۸ میس جلد اصفحه ۵۵۲
Page 686
۶۷۱
کے کیمپ میں چلے جاؤ اور کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرو اور نہ اپنے آپ کو ظاہر ہونے دو حذیفہ کہتے
ہیں کہ جب میں روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بدن میں سردی کا نام ونشان تک نہیں تھا بلکہ میں
نے یوں محسوس کیا کہ گویا ایک گرم حمام میں سے گزر رہا ہوں.اور میری گھبراہٹ بالکل جاتی رہی.اس وقت رات کی تاریکی پورے طور پر اپنی حکومت جمائے ہوئے تھی.میں بالکل نڈر ہو کر مگر چپکے چپکے
کفار کے کیمپ کے اندر پہنچ گیا.اس وقت میں نے دیکھا کہ ابوسفیان ایک جگہ کھڑا ہوا آگ سینک رہا
تھا.میں نے اسے دیکھ کر جھٹ اپنی تیر کمان سیدھی کر لی اور قریب تھا کہ میں اپنا تیر چلا دیتا مگر پھر
مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا اور تیر چلانے سے رک گیا اور اگر اس وقت میں تیر چلا دیتا
تو ابوسفیان اس قدر قریب تھا کہ وہ یقینا بچ نہ سکتا.اس وقت ابوسفیان اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دے
رہا تھا اور پھر وہ میرے سامنے ہی اونٹ پر سوار ہو گیا مگر گھبراہٹ کی وجہ سے اسے اپنے اونٹ کے پاؤں تک
کھولنے یاد نہیں رہے.اس کے بعد میں واپس چلا آیا.جب میں اپنے کیمپ میں پہنچا.اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ
کے فارغ ہونے تک انتظار کیا اور پھر آپ کو سارے واقعہ کی اطلاع دی جس پر آپ نے خدا کا شکر ادا کیا
اور فرمایا کہ یہ ہماری کسی کوشش یا طاقت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محض خدا کے فضل کی وجہ سے ہے جس نے اپنے
دم سے احزاب کو پسپا کر دیا.اس کے بعد کفار کے فرار ہونے کی خبر فورا سارے مسلمان کیمپ میں مشہور
ہوگئی.غالباً اسی موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الآنَ نَغْرُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا " یعنی " آئندہ ہم
قریش کے خلاف نکلیں گے مگر انہیں ہمارے خلاف نکلنے کی ہمت نہیں ہوگی.“
الغرض کم و بیش ہیں دن کے محاصرہ کے بعد کفار کا لشکر مدینہ سے بے نیل مرام واپس چلا گیا اور
بنو قریظہ جو ان کی مدد کے لئے نکلے تھے وہ بھی اپنے قلعہ میں واپس آگئے.اس لڑائی میں مسلمانوں کا
جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا یعنی صرف پانچ چھ آدمی شہید ہوئے مگر قبیلہ اوس کے رئیس اعظم سعد بن معاذ کو
ایسا کاری زخم آیا کہ وہ بالآخر اس سے جانبر نہ ہو سکے اور یہ نقصان مسلمانوں کے لئے ایک نا قابل تلافی
ل ابن ہشام
: مسلم حالات غزوہ خندق
بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ خندق
: مسلم حالات غزوہ خندق
ے : زرقانی
: ابن ہشام وطبری و زرقانی
ی خمیس جلد اصفحه ۵۵۳
Page 687
۶۷۲
نقصان تھا.کفار کے لشکر میں سے صرف تین آدمی قتل ہوئے لیکن اس جنگ میں قریش کو کچھ ایسا دھکا لگا کہ
اس کے بعد ان
کو پھر کبھی مسلمانوں کے خلاف اس طرح جتھہ بنا کر نکلنے یامدینہ پر حملہ آور ہونے کی ہمت
نہیں ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی.لشکر کفار کے چلے جانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو واپسی کا حکم دیا اور مسلمان
میدان کارزار سے اٹھ کر مدینہ میں داخل ہو گئے لیکن ابھی آپ اپنے گھر میں پہنچے ہی تھے کہ بنو قریظہ کے
ساتھ لڑائی کی صورت پیدا ہو گئی اور بغیر اس کے کہ آپ مدینہ میں ایک رات بھی آرام کی گزار سکیں آپ کو
ان کے مقابلہ کے لئے گھر سے نکلنا پڑا مگر اس کی تفصیل آگے آتی ہے.جنگ خندق یا احزاب جو اس طرح غیر متوقع اور نا گہانی طور پر اختتام کو پہنچی ایک نہایت ہی
خطر ناک جنگ تھی.اس سے بڑھ کر کوئی ہنگامی مصیبت اس وقت تک مسلمانوں پر نہیں آئی تھی اور نہ ہی
اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اتنی بڑی مصیبت ان پر آئی.یہ ایک خطر ناک
زلزلہ تھا جس نے اسلام کی عمارت کو جڑ سے ہلا دیا اور جس کے مہیب مناظر کو دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھیں
پتھرا گئیں اور ان کے کلیجے منہ کو آنے لگ گئے اور کمزور لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس اب خاتمہ ہے اور اس
خطرناک زلزلے کے دھکے کم و بیش ایک ماہ تک ان پر آتے رہے اور کئی ہزار خونخوار درندوں نے ان کے
گھروں کا محاصرہ کر کے ان کی زندگیوں کو تلخ کئے رکھا اور اس مصیبت کی تلخی کو بنو قریظہ کی غداری نے
دگنا کر دیا اور اس سارے فتنہ کی تہ میں بنو نضیر کے وہ محسن کش یہودی تھے جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے احسان کر کے ان کو مدینہ سے امن وامان کے ساتھ نکل جانے کی اجازت دے دی تھی.یہ انہی
یہودی رؤساء کی اشتعال انگیزی تھی جس سے صحرائے عرب کے تمام نامور قبیلے عداوت اسلام کے نشے
میں مخمور ہوکر مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لئے مدینہ پر جمع ہو گئے تھے اور یہ قطعی طور پر یقینی ہے کہ
اگر اس وقت ان وحشی درندوں کو شہر میں داخل ہو جانے کا موقع مل جاتا تو ایک واحد مسلمان بھی زندہ نہ
بچتا اور کسی پاکباز مسلم خاتون کی عزت ان لوگوں کے ناپاک حملوں سے محفوظ نہ رہتی.مگر یہ محض اللہ تعالیٰ
کا فضل اور اس کی قدرت کا غیبی ہاتھ تھا کہ اس ٹڈی دل کو بے نیل مرام واپس ہونا پڑا.اور مسلمان
شکر وامتنان کے ساتھ امن واطمینان کا سانس لیتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس آگئے.مگر بنو قریظہ کا
خطرہ ابھی تک اسی طرح قائم تھا.یہ لوگ نہایت خطرناک صورت میں اپنی غداری کا مظاہرہ کر کے اب
امن وامان کے ساتھ اپنے قلعوں میں محفوظ ہو گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ اب کوئی شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا
Page 688
۶۷۳
لیکن بہر حال ان کے فتنہ کا سد باب ضروری تھا کیونکہ ان کا وجود مدینہ میں مسلمانوں کے لئے ہرگز ایک
مار آستین سے کم نہ تھا.اور دوسری طرف بنو نضیر کا تجربہ بتا تا تھا کہ یہ سانپ ایسا ہے کہ اسے گھر سے باہر
نکالنا بھی ایسا ہی خطرناک ہے جیسا کہ اسے اپنے گھر میں رہنے دینا.
Page 689
۶۷۴
بنو قریظہ کی غداری اور مدینہ میں یہود کا خاتمہ
قانون شادی و طلاق
غزوہ بنوقریظہ ذوقعده ۵ ہجری مطابق مارچ واپریل ۶۲۷ء جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ خندق سے فارغ ہو کر شہر
میں واپس تشریف لائے تو ابھی آپ بمشکل ہتھیار وغیرہ اتار کر نہانے دھونے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ
آپ کو خدا کی طرف سے کشفی رنگ میں یہ بتایا گیا کہ جب تک بنو قریظہ کی غداری اور بغاوت کا فیصلہ
نہ ہو جاتا آپ کو ہتھیار نہیں اتارنے چاہئے تھے اور پھر آپ کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ بلا تو قف بنوقریظہ
کی طرف روانہ ہو جائیں.اس پر آپ نے صحابہ میں عام اعلان کروا دیا کہ سب لوگ بنوقریظہ کے قلعوں
کی طرف روانہ ہو جا ئیں اور نماز عصر وہیں پہنچ کر ادا کی جاوے.اور آپ نے حضرت علیؓ کو صحابہ کے
ایک دستے کے ساتھ فوراً آگے روانہ کر دیا.جب حضرت علی وہاں پہنچے تو بجائے اس کے کہ بنو قریظہ (جن میں غزوہ خندق کے بعد بنونضیر کا
رئیس اعظم اور فتنہ کا بانی مبانی حیی بن اخطب بھی اپنے وعدہ کے مطابق آکر شامل ہو گیا تھا ) اپنی
غداری و بغاوت پر اظہار ندامت کر کے عفو ورحم کے طالب بنتے انہوں نے برملا طور پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو گالیاں دیں.اور کمال بے حیائی اور کمینگی کے طریق پر ازواج مطہرات کے متعلق بھی نہایت
ناگوار بد زبانی کی.حضرت علی اور ان کے دستے کے روانہ ہو چکنے کے تھوڑی دیر بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلح
ہو کر مدینہ سے روانہ ہوئے.اس وقت آپ ایک گھوڑے پر سوار تھے اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت
بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ قریظہ ہے : ابن ہشام وطبری : سيرة حلبيه
Page 690
۶۷۵
آپ کے ساتھ تھی.جب آپ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو حضرت علی نے جو تھوڑی دور تک
آپ کے استقبال کے لئے واپس آگئے تھے آپ سے عرض کیا کہ 'یا رسول
اللہ ! میرے خیال میں آپ کو
خود آگے تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ انشاء اللہ کافی ہوں گے.آپ سمجھ گئے اور
فرمانے لگے ” کیا بنوقریظہ نے میرے متعلق کوئی بدزبانی کی ہے؟“ حضرت علی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ !
آپ نے فرمایا.خیر ہے چلو قَدْ اُوْذِى مُوسَى بِاَكْثَرَ مِنْ هَذَا.یعنی " موسیٰ کو ان لوگوں کی طرف
سے اس سے بھی زیادہ تکالیف پہنچی تھیں.غرض آپ آگے بڑھے اور بنو قریظہ کے ایک کنوئیں پر پہنچ کر
ڈیرہ ڈال دیا.کے
شروع شروع میں تو یہودی لوگ سخت تمرد اور غرور ظاہر کرتے رہے حتی کہ چند مسلمان جو ان کے قلعہ
کی دیوار کے پاس ہو کر ذرا آرام کرنے بیٹھے تھے ان پر ایک یہودی عورت بناتہ نامی نے قلعہ کے اوپر سے
ایک بھاری پتھر پھینک کر ان میں سے ایک آدمی خلاد نامی کو شہید کر دیا اور باقی مسلمان بچ گئے " لیکن جوں
جوں وقت گزرتا گیا ان کو محاصرہ کی سختی اور اپنی بے بسی کا احساس ہونا شروع ہوا اور بالآخر انہوں نے آپس
میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہئے.اس مشورہ میں ان کے رئیس کعب بن اسد نے ان کے سامنے تین
تجاویز پیش کیں اور کہا کہ ان میں سے جو بھی تمہیں پسند ہوا سے اختیار کرلو.پہلی تجویز یہ ہے، کہ ہم
محمد پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں کیونکہ اگر سچ پوچھا جاوے تو محمد کی صداقت عیاں ہو چکی ہے اور ہماری
کتب میں بھی اس کی تصدیق پائی جاتی ہے اور جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو لازماً یہ جنگ رک جائے
گی.مگر لوگوں نے اس تجویز کو سختی کے ساتھ رد کر دیا اور کہا ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے.جس پر کعب نے
کہا کہ ”پھر میرا دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اور عورتوں
کو قتل کر دیں اور پھر عواقب کی طرف سے
بے فکر ہوکر تلوار میں لیں اور میدان میں نکل جائیں اور پھر جو ہو سو ہو.لوگوں نے کہا یہ بھی ہمیں منظور
نہیں کیونکہ بچوں اور عورتوں کو مار کر ہماری زندگی کیا رہے گی.کعب نے جواب دیا کہ اچھا اگر یہ بھی منظور
نہیں تو میری آخری تجویز یہ ہے کہ آج سبت کی رات ہے اور محمد اور اس کے اصحاب آج اپنے آپ کو ہماری
طرف سے امن میں سمجھتے ہوں گے پس آج رات ہم قلعہ سے نکل کر محمد اور اس کے ساتھیوں پر شب خون
ماریں اور بعید نہیں کہ ان کی غفلت کی وجہ سے ہم انہیں مغلوب کرلیں.“ مگر بنوقریظہ نے اس تجویز کے
: حضرت علی کا منشاء یہ تھا کہ آپ کو بنو قریظہ کی گالیاں سن کر خواہ نخواہ ملال ہو گا اس لئے آپ نہ جائیں تو بہتر ہے
ابن سعد جلد ۲ صفحه ۵۶،۵۵
خمیس جلد اصفحه ۵۵۹ وطبری ۱۵۰۱
ابن ہشام
Page 691
۶۷۶
ماننے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ آگے ہی ہماری قوم سبت کی بے حرمتی کی وجہ سے مسخ کی جاچکی ہے پس
اب ہم مزید بے حرمتی کر کے اپنی تباہی کا خود بیج نہیں ہو سکتے.اس طرح کعب کی ساری تجاویز رد
ہوگئیں اور معاملہ وہیں کا وہیں رہا.آخر جب بنو قریظہ محاصرہ کی سختی سے تنگ آگئے تو انہوں نے یہ تجویز کی کہ کسی ایسے مسلمان کو جوان
سے تعلقات رکھتا ہو اور اپنی سادگی کی وجہ سے ان کے داؤ میں آسکتا ہو اپنے قلعہ میں بلائیں اور اس سے یہ
پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے متعلق کیا ارادہ ہے تا کہ وہ اس کی روشنی
میں آئندہ طریق عمل تجویز کرسکیں.چنانچہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایلچی
روانہ کر کے یہ درخواست کی کہ ابولبابہ بن منذر انصاری کو ان کے قلعہ میں بھجوایا جاوے تا کہ وہ اس سے
مشورہ کر سکیں.آپ نے ابولبابہ کو اجازت دی اور وہ ان کے قلعہ میں چلے گئے.اب رؤساء بنو قریظہ نے
یہ تجویز کی ہوئی تھی کہ جو نہی کہ ابولبابہ قلعہ کے اندر داخل ہو سب یہودی عورتیں اور بچے روتے اور چلاتے
ہوئے ان کے اردگرد جمع ہو جائیں اور اپنی مصیبت اور تکلیف کا ان کے دل پر پورا پورا اثر پیدا کرنے کی
کوشش کی جائے.چنانچہ ابولبابہ پر یہ داؤ چل گیا اور وہ قلعہ میں جاتے ہی ان کی مصیبت کا شکار ہو گئے
اور بنو قریظہ کے اس سوال پر کہ اے ابولبابہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے کیا ہم محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے فیصلہ
پر اپنے قلعوں سے اتر آویں.ابولبابہ نے بے ساختہ جواب دیا ”ہاں“ مگر ساتھ ہی اپنے گلے پر ہاتھ
پھیر کر اشارہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قتل کا حکم دیں گے.حالانکہ یہ بالکل غلط تھا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کوئی ایسا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا مگر ان کی مصیبت کے مظاہرہ سے متاثر
ہو کر ابولبابہ کا خیال آلام و مصائب کی رو میں ایسا بہا کہ موت سے ورے ورے نہیں ٹھہرا اور ابولبابہ کی
یہ غلط ہمدردی (جس کی وجہ سے وہ بعد میں خود بھی نادم ہوئے اور اس ندامت میں انہوں نے اپنے آپ کو
جا کر مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے
خود جا کر انہیں کھولا) بنو قریظہ کی تباہی کا باعث بن گئی اور وہ اس بات پر ضد کر کے جم گئے کہ ہم محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے فیصلہ پر نہیں اتریں گے ہے
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جاری رہی اور آخر کم و بیش بیس دن کے محاصرہ کے بعد یہ بد بخت یہود ایک
ایسے شخص کو حکم مان کر اپنے قلعوں سے اترنے پر رضا مند ہوئے جو باوجود ان کا حلیف ہونے کے ان کی
ل ابن ہشام و نیز طبری صفحه ۷ ۱۴۸، ۱۳۸۸
: طبری صفحه ۱۴۸۸، ۱۴۹۰،۱۳۸۹ و میس جلد اصفحه ۵۵۶
Page 692
722
کارروائیوں کی وجہ سے ان کے لئے اپنے دل میں کوئی رحم نہیں پاتا تھا اور جو گو عدل وانصاف کا مجسمہ تھا مگر
اس کے قلب میں رحمۃ للعالمین کی سی شفقت اور رافت نہیں تھی.تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قبیلہ اوس
بنوقریظہ کا قدیم حلیف تھا اور اس زمانہ میں اس قبیلہ کے رئیس سعد بن معاذ تھے جو غزوہ خندق میں زخمی
ہو کر اب مسجد کے صحن میں زیر علاج تھے.اس قدیم جتھہ داری کا خیال کرتے ہوئے بنوقریظہ نے کہا کہ ہم
سعد بن معاذ کو اپنا حکم مانتے ہیں.جو فیصلہ بھی وہ ہمارے متعلق کریں وہ ہمیں منظور ہوگا.لیکن یہود میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اس قومی فیصلہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو مجرم
یقین کرتے تھے اور دل میں اسلام کی صداقت کے قائل ہو چکے تھے.ایسے لوگوں میں سے بعض آدمی جن
کی تعداد تاریخی روایات میں تین بیان ہوئی ہے بطیب خاطر اسلام قبول کر کے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو گئے.ایک اور شخص تھا وہ مسلمان تو نہیں ہوا مگر وہ اپنی قوم کی غداری پر اس
قدر شرمندہ تھا کہ جب بنوقریظہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھانی تو وہ یہ کہتا ہوا
کہ ” میری قوم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غداری کی ہے میں اس غداری میں شامل نہیں
ہوسکتا.مدینہ چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا تھا کے مگر باقی قوم آخر تک اپنی ضد پر قائم رہی اور سعد کو اپنا ثالث
بنانے پر اصرار کیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منظور فرمایا.اور اس کے بعد آپ نے چند
انصاری صحابیوں کو سعد کے لانے کے لئے روانہ فرمایا.سعد سوار ہو کر آئے اور راستہ میں قبیلہ اوس کے بعض
لوگوں نے ان سے اصرار کے ساتھ اور بار بار یہ درخواست کی کہ قریظہ ہمارے حلیف ہیں جس طرح
خزرج نے اپنے حلیف قبیلہ بنو قینقاع کے ساتھ نرمی کی تھی تم بھی قریظہ سے رعایت کا معاملہ کرنا اور انہیں
سخت سزا نہ دینا.سعد بن معاذ پہلے تو خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے ،لیکن جب ان کی طرف
سے زیادہ اصرار ہونے لگا تو سعد نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ سعد اس وقت حق وانصاف کے معاملہ میں
کسی ملامت گر کی ملامت کی پروا نہیں کر سکتا." یہ جواب سن کر لوگ خاموش ہو گئے.جب سعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ
یعنی اپنے رئیس کے لئے اٹھو اور سواری سے نیچے اترنے میں انہیں مدد دو.“ جب سعد سواری سے اتر کر
ابن ہشام وطبری و ابن سعد نیز بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ قریظہ
ابن ہشام و بخاری کتاب المغازی باب خبر النضیر
: طبری صفحه ۱۴۹۲
66
: طبرانی صفحه ۱۴۹۰
Page 693
۶۷۸
،،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا ”سعد! بنوقریظہ نے
تمہیں حکم مانا ہے اور ان کے متعلق جو تم فیصلہ کرو انہیں منظور ہوگا.اس پر سعد نے اپنے قبیلے اوس کے
لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر کہا عَلَيْكُمْ بِذَالِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيْثَاقَهُ إِنَّ الْحُكْمَ فِيهِمْ بِمَا
حَكَمُتُ ـ " کیا تم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ پختہ عہد کرتے ہو کہ تم بہر حال اس فیصلہ پر عمل کرنے
کے پابند ہو گے جو میں بنو قریظہ کے متعلق کروں؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں.پھر سعد نے
اس جہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے
کہا.وَعَلَى مَنْ هَهُنَا.یعنی وہ صاحب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں کیا وہ بھی ایسا ہی وعدہ کرتے ہیں
کہ وہ بہر حال میرے فیصلہ کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوں گے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کے
اس عہد و پیمان کے بعد سعد نے اپنا فیصلہ سنایا جو یہ تھا کہ بنو قریظہ کے مقاتل یعنی جنگجو لوگ قتل
کر دئے جائیں اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر لئے جائیں اور ان کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کر دئے
جائیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا تو بے ساختہ فرمایا.لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ -
یعنی " تمہارا یہ فیصلہ ایک خدائی تقدیر ہے.جو ٹل نہیں سکتی اور ان الفاظ سے آپ کا یہ مطلب تھا کہ
بنو قریظہ کے متعلق یہ فیصلہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ اس میں صاف طور پر خدائی تصرف کام کرتا ہوا
نظر آتا ہے اور اس لئے آپ کا جذ بہ رحم اسے روک نہیں سکتا اور یہ واقعی درست تھا کیونکہ بنوقریظہ کا ابولبابہ
کو اپنے مشورہ کے لئے بلانا اور ابولبابہ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل جانا جو سراسر بے بنیاد تھی اور پھر
بنوقریظہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننے سے انکار کرنا اور اس خیال سے کہ قبیلہ اوس کے لوگ
ہمارے حلیف ہیں اور ہم سے رعایت کا معاملہ کریں گے سعد بن معاذ رئیس اوس کو اپنا حکم مقرر کرنا.پھر سعد کا حق وانصاف کے رستے میں اس قدر پختہ ہو جانا کہ عصبیت اور جتھہ داری کا احساس دل سے
بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ بنوقریظہ عن ابی سعید خدری
: مؤرخین لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ لیتے ہوئے سعد کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ آپ کی طرف
نظر اٹھا کر دیکھیں یا آپ سے مخاطب ہو کر دریافت کریں.ے ابن ہشام وطبری و کتاب الخراج ابو یوسف صفحه ۱۲۴
بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ قریطه
Page 694
۶۷۹
بالکل محو ہو جاوے اور بالآخر سعد کا اپنے فیصلہ کے اعلان سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا
پختہ عہد لے لینا کہ بہر حال اس فیصلہ کے مطابق عمل ہوگا.یہ ساری باتیں اتفاقی نہیں ہوسکتیں اور یقیناً
اس کی تہ میں خدائی تقدیر اپنا کام کر رہی تھی اور یہ فیصلہ خدا کا تھا نہ کہ سعد کا.ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنو قریظہ کی بدعہدی اور غداری اور بغاوت اور فتنہ و فساد اور قتل و خونریزی کی وجہ
سے خدائی عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ ان کے جنگجولوگوں کو دنیا سے مٹا دیا جاوے.چنانچہ
ابتداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوہ کے متعلق غیبی تحریک ہونا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک
خدائی تقدیر تھی.مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کے رسول کے ذریعہ سے یہ فیصلہ جاری ہو اور اس لئے اس
نے نہایت پیچ در پیچ غیبی تصرفات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل الگ رکھا اور سعد بن معاذ کے
ذریعہ اس فیصلہ کا اعلان کروایا اور فیصلہ بھی ایسے رنگ میں کروایا کہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں
بالکل دخل نہیں دے سکتے تھے کیونکہ آپ وعدہ فرما چکے تھے کہ آپ بہر حال اس فیصلہ کے پابند رہیں گے
اور پھر چونکہ اس فیصلہ کا اثر بھی صرف آپ کی ذات پر نہیں پڑتا تھا بلکہ تمام مسلمانوں پر پڑتا تھا اس لئے
آپ اپنا یہ حق نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی رائے سے خواہ وہ کیسی ہی عفو ورحم کی طرف مائل ہو اس فیصلہ کو بدل
دیں یہی خدائی تصرف تھا جس کی طاقت سے متاثر ہو کر آپ کے منہ سے بے اختیار طور پر یہ الفاظ نکلے
کہ قَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ یعنی اے سعد! تمہارا یہ فیصلہ تو خدائی تقدیر معلوم ہوتی ہے جس کے
بدلنے کی کسی کو طاقت نہیں.یہ الفاظ کہہ کر آپ خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور شہر کی طرف چلے آئے اور اس وقت آپ کا دل اس
خیال سے دردمند ہو رہا تھا کہ ایک قوم جس کے ایمان لانے کی آپ کے دل میں بڑی خواہش تھی اپنی
بد کردار یوں کی وجہ سے ایمان سے محروم رہ کر خدائی قہر و عذاب کا نشانہ بن رہی ہے اور غالباً اسی موقع پر
آپ نے یہ حسرت بھرے الفاظ فرمائے کہ لَوْامَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَا مَنَتْ بِيَ الْيَهُودُ يعنى
اگر یہود میں سے مجھ پر دس آدمی یعنی دس بارسوخ آدمی بھی ایمان لے آتے تو میں خدا سے امید رکھتا تھا
کہ یہ ساری قوم مجھے مان لیتی.اور خدائی عذاب سے بچ جاتی.وہاں سے اٹھتے ہوئے آپ نے یہ حکم دیا کہ بنو قریظہ کے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ علیحدہ
کر دیا جاوے.چنانچہ دونوں گروہوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے مدینہ میں لایا گیا اور شہر میں دو الگ الگ
ا بخاری باب اتیان الیہود النبی صلعم
Page 695
۶۸۰
مکانات میں جمع کر دیا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت صحابہ نے (جن میں سے غالباً کئی
لوگ خود بھو کے رہے ہوں گے ) بنو قریظہ کے کھانے کے لئے ڈھیروں ڈھیر پھل مہیا کیا اور لکھا ہے کہ
یہودی لوگ رات بھر پھل نوشی میں مصروف رہے.دوسرے دن صبح کو سعد بن معاذ کے فیصلہ کا اجرا ہونا تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مستعد
آدمی اس کام کی سرانجام دہی کے لئے مقرر فرمادے اور خود بھی قریب ہی ایک جگہ میں تشریف فرما
ہو گئے.تا کہ اگر فیصلہ کے اجرا کے دوران میں کوئی بات ایسی پیدا ہو جس میں آپ کی ہدایت کی ضرورت
ہو تو آپ بلا توقف ہدایت دے سکیں نیز یہ کہ اگر کسی مجرم کے متعلق کسی شخص کی طرف سے رحم کی اپیل ہو تو
اس میں آپ فوراً فیصلہ صادر فرماسکیں کیونکہ گوسعد کے فیصلہ کی اپیل عدالتی رنگ میں آپ کے سامنے پیش
نہیں ہو سکتی تھی مگر ایک بادشاہ یا صدر جمہوریت کی حیثیت میں آپ کسی فرد کے متعلق کسی خاص وجہ کی بنا پر
رحم کی اپیل ضرورسن سکتے تھے.آپ نے بتقاضائے رحم یہ بھی حکم صادر فرمایا کہ مجرموں کو ایک ایک کر کے
علیحدہ علیحد قتل کیا جاوے.یعنی ایک کے قتل کے وقت دوسرے مجرم پاس موجود نہ ہوں.چنانچہ ایک ایک
مجرم کو الگ الگ لایا گیا.اور بموجب فیصلہ سعد بن معاذ قتل کیا گیا.جب حی بن اخطب رئیس بنو نضیر آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ
”اے محمد مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ میں نے تمہاری مخالفت کیوں کی لیکن بات یہ ہے کہ جو خدا کو چھوڑتا
ہے خدا بھی اسے چھوڑ دیتا ہے.پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا’ خدا کے حکم کے آگے کوئی چارہ نہیں
ہے.یہ اسی کا حکم اور اسی کی تقدیر ہے.جب کعب بن اسد رئیس قریظہ کو میدان قتل میں لایا گیا تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ مسلمان ہو جانے کی تحریک کی.اس نے کہا اے ابو القاسم !
میں مسلمان تو ہو جا تا مگر لوگ کہیں گے موت سے ڈر گیا.پس مجھے یہودی مذہب پر ہی مرنے دو.ایک شخص زبیر بن باطیا روسائے قریظہ میں سے تھا.اس نے ایک مسلمان ثابت بن قیس نامی پر
کسی زمانہ میں کوئی احسان کیا تھا.ثابت نے اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ
اسے چھوڑ دیا جاوے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ” بہت اچھا! اسے چھوڑ دو.‘ ثابت نے جا کر
زبیر کوخوشخبری دی کہ تجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سفارش پر چھوڑ دیا ہے.زبیر نے کہا
زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۳۶
،،
زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۳۶
966
: ابن ہشام وابن سعد و طبری
طبری وابن ہشام
سيرة حلبیہ حالات غزوہ قریظہ
Page 696
۶۸۱
میرے بیوی بچے تو قید میں ہیں میں قتل سے بچ کر کیا کروں گا.ثابت پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس گیا اور کہا کہ زبیر یوں کہتا ہے.آپ نے فرمایا اس کے بیوی بچوں کو بھی آزاد کر دو.“
ثابت نے جا کر ز بیر کو پھر خوشخبری دی.جس پر اس نے کہا میرا مال تو مسلمانوں کے قبضہ میں جاچکا ہے
میں صرف بیوی بچوں کو لے کر کیا کروں گا.ثابت نے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور
آپ نے زبیر کے مال کے بھی واپس دئے جانے کا حکم دے دیا.اب ثابت بہت خوش خوش زبیر کے
پاس گیا کہ لواب تمہارا مال بھی تمہیں واپس مل جائے گا.اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ہمارے سردار کعب بن
اسد اور یہودان عرب کے رئیس حی بن اخطب کا کیا حال ہے.ثابت نے کہا کہ وہ تو قتل کئے جاچکے.اس نے کہا جب یہ لوگ قتل ہو گئے تو پھر میں نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے.چنانچہ مقتل میں گیا اور تلوار
کے سامنے اپنی گردن رکھ دی.ایک اور یہودی رفاعہ نامی تھا اس نے ایک رحم دل مسلمان خاتون کی منت سماجت کر کے اسے اپنی
سفارش میں کھڑا کر لیا.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان خاتون کی سفارش پر رفاعہ کو بھی
معاف فرما دیا.غرض اس وقت جس شخص کی بھی سفارش آپ کے پاس کی گئی آپ نے اسے فور أمعاف
کر دیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سعد کے فیصلہ کی وجہ سے مجبور تھے ورنہ آپ کا قلبی میلان ان کے
قتل کئے جانے کی طرف نہیں تھا.مقتولین میں ایک یہودی عورت بھی تھی.جس نے محاصرہ کے وقت قلعہ پر سے ایک پتھر گرا کر ایک
مسلمان کو شہید کیا تھا.پس چونکہ اس نے اس باغیانہ جنگ میں عملی حصہ لیا تھا اور سعد کا یہ فیصلہ تھا کہ
جنگ میں حصہ لینے والوں کو قتل کیا جاوے اور چونکہ اس عورت کی طرف سے اپنی غداری اور بغاوت اور
فعل قتل کے متعلق اظہار ندامت بھی نہیں ہوا اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی رحم کی
اپیل ہوئی اس لئے اسے بھی سعد کے حکم کے مطابق مقتل میں لا کر قتل کیا گیا.غرض اس طرح کم و بیش
چار سو آدمی اس دن سعد کے فیصلہ کے مطابق قتل کئے گئے.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو
حکم دے کر ان مقتولین کو اپنے انتظام میں دفن کر وا دیا.طبری وابن ہشام
: ابن ہشام
بنو قریظہ جہاں سعد کے فیصلہ میں مقاتل یعنی جنگ میں حصہ لینے والا کا لفظ استعمال ہوا ہے.طبری وابن ہشام
: دیکھو صحیح بخاری حالات
۵: ترمذی ابواب الجهاد والسیر وابن ہشام فی ذکر ا مر محیصہ وحویصتہ
Page 697
۶۸۲
بچے اور عور تیں جو سعد کے فیصلہ کے مطابق قید کر لئے گئے تھے ان کے متعلق بعض روایات سے پتہ لگتا
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجد کی طرف بھجوا دیا تھا جہاں بعض نجدی قبائل نے ان کا فدیہ ادا
کر کے انہیں چھڑا لیا تھا اور اس رقم سے مسلمانوں نے اپنی جنگی ضروریات کے لئے گھوڑے اور ہتھیار
خریدے تھے.اگر ایسا ہوا ہو تو کوئی بعید نہیں کیونکہ نجدی قبائل اور بنو قریظہ آپس میں حلیف تھے اور غزوہ
قریظہ سے صرف چند دن قبل ہی وہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف اکٹھے لڑ چکے تھے اور دراصل اہل
نجد ہی کی انگیخت پر بنوقریظہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا.پس اگر
نجد والوں نے اپنے حلیف بنو قریظہ کے قیدیوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہو تو جائے تعجب نہیں.لیکن صحیح روایات سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قیدی مدینہ میں ہی رہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
حسب دستور مختلف صحابیوں کی نگرانی میں تقسیم فرما دیا تھا.تے اور پھر ان میں سے بعض نے اپنا فدیہ ادا کر کے
رہائی حاصل کر لی تھی..اور بعض کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یونہی بطور احسان کے چھوڑ دیا تھا.ہے
اور پھر یہ لوگ بعد میں آہستہ آہستہ بطیب خاطر خود مسلمان ہو گئے چنانچہ ان میں سے عطیہ قرظی اور
عبدالرحمن بن زبیر بن باطیا اور کعب بن سلیم اور محمد بن کعب کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں اور یہ سب م
مسلمان
ہو گئے تھے اور ان میں مؤخر الذکر شخص تو ایک بڑے پایہ کا مسلمان گزرا ہے.ریحانہ کا غلط واقعہ بعض مؤرخین لکھتے ہیں کہ بنو قریظہ کے قیدیوں میں ایک عورت ریحانہ تھی جسے
آنحضرت نے لونڈی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا اور اسی روایت کی بنا پر
سرولیم میور نے اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت دل آزارطعن کیا ہے مگر حقیقت یہ
ہے کہ یہ روایت بالکل غلط اور بے بنیاد ہے.اوّل تو صحیح بخاری کی محولہ بالا روایت جس میں یہ بیان کیا گیا
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم فرما دیا تھا اس روایت کو غلط ثابت
کرتی ہے.اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیدی عورت اپنے گھر کے لئے الگ کر لی تھی تو طبعا اس
موقع پر بخاری کی روایت میں اس کا ذکر ہونا چاہئے تھا مگر بخاری میں اس کا اشارہ تک نہیں ہے.علاوہ
طبری وابن ہشام
: سيرة حلبیہ جلد ۲ صفحه ۳۷۱
بخاری کتاب المغازی باب حدیث بنی النضیر و خمیس جلد اصفحه ۵۷۰
۴: ابن سعد جلد ۲ صفحه ۵۴
۵: دیکھو تہذیب التہذیب اصابہ اسدالغابہ واستیعاب حالات اشخاص مذکورہ
بخاری کتاب المغازی باب حدیث بنی النضیر
Page 698
۶۸۳
ازیں دوسری صحیح روایات سے معین طور پر ثابت ہے کہ ریحانہ ان قیدیوں میں سے تھی جنہیں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور احسان کے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد ریحانہ مدینہ سے رخصت ہو کر اپنے میکے
کے خاندان ( بنو نضیر ) میں چلی گئی تھی اور پھر وہیں رہی اور علامہ ابن حجر نے جو اسلام کے چوٹی کے محققین
میں سے ہیں اسی روایت کو صحیح قرار دیا ہے.یا لیکن اگر یہ تسلیم بھی کیا جاوے کہ ریحانہ کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے خود اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا تو تب بھی یقینا وہ آپ کی بیوی تھی نہ کہ لونڈی.چنانچہ جن
مؤرخین نے ریحانہ کے متعلق یہ روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سرپرستی میں
لے لیا تھا ان میں سے اکثر نے ساتھ ہی یہ صراحت کی ہے کہ آپ نے اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ
شادی کر لی تھی.چنانچہ ابن سعد نے ایک روایت خود ریحانہ کی زبانی نقل کی ہے جس میں وہ بیان کرتی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا تھا اور پھر میرے مسلمان ہو جانے پر میرے ساتھ
شادی فرمائی تھی اور میرا مہر بارہ اوقیہ مقرر ہوا تھا اور ابن سعد نے اس روایت کے مقابلہ میں اس دوسری
روایت کو جس پر سر ولیم میور نے بنیادرکھی ہے صراحت کے ساتھ غلط اور خلاف واقعہ قرار دیا ہے اور لکھا ہے
کہ یہی اہل علم کی تحقیق ہے.الغرض اوّل تو جیسا کہ بخاری کی روایت سے استدلال ہوتا ہے اور اصابہ میں تصریح کی گئی ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ کو اپنی سر پرستی میں لیا ہی نہیں بلکہ اسے آزاد کر دیا تھا.جس کے بعد وہ
اپنے خاندان میں جا کر آباد ہو گئی تھی.دوسرے اگر اس روایت کو تسلیم بھی کیا جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا تو تب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر کے
اس کے ساتھ شادی فرمائی تھی اور اسے لونڈی کے طور پر نہیں رکھا.علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے
کہ ریحانہ کے نام اور حسب نسب اور قبیلہ وغیرہ کے متعلق روایات میں اس قدر اختلاف ہے تا کہ اس کے
وجود ہی کے متعلق شبہ کرنا غالباً غیر معقول نہیں سمجھا جا سکتا.خصوصاً جبکہ اس بات کو مدنظر رکھا جاوے کہ
اسے ایک ایسے شخص کی بیوی کہا جاتا ہے جو دنیا میں یقینا سب سے زیادہ تاریخی شخص ہے واللہ اعلم.اصابه جلده اصفحه ۵۹۳ ذکر ریحانه
دیکھو ابن سعد جلد ۸ صفحه ۹۳ حالات ریحانه وزرقانی جلد ۲ صفحه ۱۳۷
: زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۸۴٬۲۸۳
Page 699
۶۸۴
بنوقریظہ کا واقعہ اور غیر
مسلم مؤرخین بنوقریظہ کے واقعہ کے متعلق بعض غیر مسلم مؤرخین نے
نہایت ناگوار طریقے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
خلاف حملے کئے ہیں اور ان کم و بیش چار سو یہودیوں کی سزائے قتل کی وجہ سے آپ کو ایک نعوذ باللہ
ظالم و سفاک فرمانروا کے رنگ میں پیش کیا ہے اس اعتراض کی بنا محض مذہبی تعصب پر واقع ہے جس سے
جہاں تک کم از کم اسلام اور بانی اسلام کا تعلق ہے بہت سے مغربی روشنی میں تربیت یافتہ مؤرخ بھی
آزاد نہیں ہو سکے.اس اعتراض کے جواب میں اول تو یہ بات رکھنی چاہئے کہ بنو قریظہ کے متعلق جس فیصلہ کو ظالمانہ
کہا جاتا ہے وہ سعد بن معاذ کا فیصلہ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گز نہیں تھا اور جب وہ آپ کا فیصلہ
ہی نہیں تھا تو اس کی وجہ سے آپ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا.دوم یہ فیصلہ حالات پیش آمدہ کے ماتحت
ہرگز غلط اور ظالمانہ نہیں تھا جیسا کہ ابھی ثابت کیا جائے گا.سوم یہ کہ اس عہد کی وجہ سے جو سعد نے فیصلہ
کے اعلان سے قبل آپ سے لیا تھا آپ اس بات کے پابند تھے کہ بہر حال اس کے مطابق عمل کرتے.چہارم یہ کہ جب خود مجرموں نے اس فیصلہ کو قبول کیا اور اس پر اعتراض نہیں اٹھایا اور اسے اپنے لئے ایک
خدائی تقدیر سمجھا جیسا کہ حیی بن اخطب کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے جو اس نے قتل کئے جانے کے وقت
کہے تو اس صورت میں آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ خواہ نخواہ اس میں دخل دینے کے لئے کھڑے ہو جاتے.سعد کے فیصلہ کے بعد اس معاملہ کے ساتھ آپ کا تعلق صرف اس قدر تھا کہ آپ اپنی حکومت کے
نظام کے ماتحت اس فیصلہ کو بصورت احسن جاری فرماویں اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے اسے ایسے رنگ
میں جاری فرمایا کہ جو رحمت و شفقت کا بہترین نمونہ سمجھا جاسکتا ہے.یعنی جب تک تو یہ لوگ فیصلہ کے اجرا
سے قبل قید میں رہے آپ نے ان کی رہائش اور خوراک کا بہتر سے بہتر انتظام فرمایا اور جب ان پر سعد کا
فیصلہ جاری کیا جانے لگا تو آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری کیا جو مجرموں کے لئے کم سے کم موجب
تکلیف تھا یعنی اول تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہ حکم دیا کہ ایک مجرم کے قتل کے
وقت کوئی دوسرا مجرم سامنے نہ ہو بلکہ تاریخ سے پتا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو مقتل میں لایا جا تا تھا ان کو
اس وقت تک علم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جب تک وہ عین مقتل میں نہ پہنچ جاتے تھے.اس
کے علاوہ جس شخص کے متعلق بھی آپ کے سامنے رحم کی اپیل پیش ہوئی آپ نے اسے فوراً قبول کر لیا اور
دیکھوطبری وابن ہشام
Page 700
۶۸۵
نہ صرف ایسے لوگوں کی جان بخشی کی بلکہ ان کے بیوی بچوں اور اموال وغیرہ کے متعلق بھی حکم دے دیا
کہ انہیں واپس دئے جائیں.اس سے بڑھ کر ایک مجرم کے ساتھ رحمت وشفقت کا سلوک کیا ہوسکتا
ہے؟ پس نہ صرف یہ کہ بنو قریظہ کے واقعہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعاً کوئی اعتراض وارد
نہیں ہو سکتا بلکہ حق یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ کے اخلاق فاضلہ اور حسن انتظام اور آپ کے فطری رحم و کرم کا
ایک نہایت بین ثبوت ہے.اب رہا اصل فیصلہ کا سوال.سو اس کے متعلق بھی ہم بلا تامل کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہر گز کسی قسم کے
ظلم و تعدی کا دخل نہیں تھا بلکہ وہ عین عدل و انصاف پر مبنی تھا.اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا
چاہئے کہ بنوقریظہ کا جرم کیا تھا اور وہ جرم کن حالات میں کیا گیا.سو تاریخ سے پتا لگتا ہے کہ جب شروع
شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے تین قبیلے
آباد تھے یعنی بنو قینقاع، قبیلہ بنو نضیر اور قبیلہ بنوقریظہ.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو
پہلا سیاسی کام کیا وہ یہ تھا کہ ان تینوں قبیلوں کے رؤساء کو بلا کر ان کے ساتھ امن و امان کا ایک معاہدہ کیا.اس معاہدہ کی شرائط یہ تھیں کہ مسلمان اور یہودی امن وامان کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے اور ایک
دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کو کسی قسم کی مدد نہیں دیں گے اور
نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے اور اگر کسی بیرونی قبیلہ یا قبائل کی طرف سے
مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اگر معاہدہ کرنے والوں میں سے کوئی شخص یا
کوئی گروہ اس معاہدہ کو توڑے گا یا فتنہ وفساد کا باعث بنے گا تو دوسروں کو اس کے خلاف ہاتھ اٹھانے کا
حق ہوگا.اور تمام اختلافات اور تنازعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے اور آپ کا فیصلہ
سب کے لئے واجب التعمیل ہوگا.مگر یہ ضروری ہوگا کہ ہر شخص یا قوم کے متعلق اسی کے مذہب اور اسی کی
شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جاوے لے
اس معاہدہ پر یہود نے کس طرح عمل کیا ؟ اس سوال کا جواب گزشتہ اوراق میں تفصیل کے ساتھ گزر
چکا ہے.سب سے پہلے قبیلہ بنو قینقاع نے بد عہدی کی اور دوستانہ تعلقات کو قطع کر کے مسلمانوں سے
جنگ کی طرح ڈالی اور مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کا کمینہ طریق اختیار کیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی اس صدارتی پوزیشن کو جو بین الاقوام معاہدہ کی رو سے آپ کو حاصل تھی نہایت متمردانہ انداز میں ٹھکرا دیا
ابن ہشام ذکر معاہدہ یہود
Page 701
۶۸۶
مگر جب وہ مسلمانوں کے سامنے مغلوب ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا اور
صرف اس قدر احتیاطی تدبیر پر اکتفا کی کہ بنو قینقاع مدینہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں
تا کہ شہر کا امن برباد نہ ہو اور مسلمان ایک مارآستین کے شر سے محفوظ ہو جا ئیں.چنانچہ قبیلہ بنوقینقاع
کے لوگ بڑے امن وامان کے ساتھ اپنے اموال اور بیوی بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ سے نکل کر
دوسری جگہ آباد ہو گئے.مگر اس واقعہ سے یہود کے باقی دو قبائل نے سبق حاصل نہ کیا بلکہ آپ کے رحم نے ان کو اور بھی
نا واجب جرأت دلا دی اور ا بھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ یہود کے دوسرے قبیلہ بنونضیر نے بھی سر اٹھایا
اور سب سے پہلے ان کے ایک رئیس کعب بن اشرف نے معاہدہ کوتو ڑ کر قریش اور دوسرے قبائل عرب
کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ساز باز شروع کی اور عرب کے ان وحشی درندوں کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف خطرناک طور پر ابھارا اور مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے اشتعال
انگیز شعر کہے کہ جس سے ملک میں مسلمانوں کے لئے ایک نہایت خطرناک صورت حال پیدا ہوگئی اور پھر
اس بد بخت نے معزز مسلمان عورتوں کا نام لے لے کر اپنے اشعار میں ان پر پھبتیاں اڑائیں اور بالآخر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ شخص اپنے
کیفر کردار کو پہنچا تو اس کا قبیلہ یک جان ہو کر مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور اس دن سے بنونضیر نے
معاہدہ کو بالائے طاق رکھ کر مسلمانوں کے خلاف ساز باز شروع کردی اور بالآخر سارے قبیلہ نے مل کر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ باندھا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ جس طرح بھی ہو آپ کو زندہ نہ چھوڑا
جاوے اور جب ان کے ان خونی ارادوں کا علم ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
کی تنبیہ اور سزا
کا طریق اختیار کیا تو وہ نہایت مغرورانہ انداز میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو گئے اور اس
جنگ میں بنوقریظہ نے ان کی اعانت کی.مگر جب بنو نضیر مغلوب ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے بنو قریظہ کو تو بالکل ہی معاف فرما دیا ہے اور بنو نضیر کو بھی مدینہ سے امن وامان کے ساتھ چلے جانے کی
اجازت دے دی.البتہ اس قدر کیا کہ انہیں ان کے اسلحہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی مگر اس
احسان کا بدلہ بنو نضیر نے یہ دیا کہ مدینہ سے باہر جا کر ان کے رؤساء نے تمام عرب کا چکر لگایا اور مختلف
قبائل عرب کو خطر ناک طور پر اشتعال دے کر ایک ٹڈی دل لشکر مدینہ پر چڑھا لائے اور سب سے یہ پختہ
بخاری حدیث بنی النفير
بخاری حدیث بنی النضیر
Page 702
YAZ
عہد لیا کہ اب جب تک اسلام کو نیست و نابود نہ کر لیں گے واپس نہیں جائیں گے.ایسے خطرناک وقت میں جس کا ایک مختصر خاکہ اوپر گزر چکا ہے.یہود کے تیسرے قبیلہ بنوقریظہ نے کیا
کیا؟ اور یہ قبیلہ وہ تھا.جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنونضیر کے موقع پر ان کی غداری
کو معاف کر کے خاص احسان کیا تھا.اور پھر دوسرا احسان ان پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ باوجود
اس کے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل بنو نضیر سے مرتبہ اور حقوق میں ادنیٰ سمجھے جاتے
تھے یعنی اگر بنونضیر کا کوئی آدمی بنوقریظہ کے ہاتھ سے قتل ہو جا تا تھا تو قاتل کو قصاص میں قتل کیا جاتا تھا،
لیکن اگر بنوقریظہ کا کوئی آدمی بنو نضیر کے ہاتھ سے قتل ہو جا تا تھا تو محض دیت کی ادائیگی کافی سمجھی جاتی تھی،
لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو دوسرے شہریوں کے ساتھ برابری کے حقوق عطا کئے.مگر با وجود ان عظیم الشان احسانوں کے بنو قریظہ نے پھر بھی غداری کی اور غداری بھی ایسے نازک وقت
میں کی جس سے زیادہ نازک وقت مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا.بنو قینقاع کی مثال ان کے سامنے تھی انہوں
نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا.بنو نضیر کا واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا انہوں نے اس سے سبق
حاصل نہیں کیا اور کیا تو کیا کیا ؟ یہ کیا کہ اپنے معاہدہ کو بالائے طاق رکھ کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
احسانات کو فراموش کر کے عین اس وقت جبکہ تین ہزار مسلمان نہایت بے سروسامانی اور بے بسی کی حالت
میں کفار کے دس پندرہ ہزار جرار اور خونخوارا شکر سے گھرے ہوئے بیٹھے تھے اور اپنی بیچارگی کو دیکھ کر ان کے
کلیجے منہ کو آرہے تھے اور موت انہیں اپنے سامنے دکھائی دیتی تھی.وہ اپنے قلعوں میں سے نکلے اور مسلمان
مستورات اور بچوں پر عقب سے حملہ آور ہو گئے اور مسلمانوں کے اتحاد سے منحرف ہو کر اس خونی اتحاد کی
شمولیت اختیار کی جس کا اصل الاصول اسلام اور بانی اسلام کو نیست و نابود کرنا تھا ہاں اس بانی اسلام کو جس
کا مدینہ میں آنے کے بعد پہلا کام یہ تھا کہ اس نے ان یہود کو اپنا دوست اور معاہد بنایا اور یہود کا پہلا کام یہ
تھا کہ انہوں نے اسے اپنا دوست اور معاہد مان کر اسے اپنی جمہوریت کا صدر تسلیم کیا.اندریں حالات
بنو قریظہ کا یہ فعل صرف ایک بدعہدی اور غداری ہی نہیں تھا بلکہ ایک خطر ناک بغاوت کا بھی رنگ رکھتا
تھا اور بغاوت بھی ایسی کہ اگر ان کی تدبیر کامیاب ہو جاتی تو مسلمانوں کی جانوں اور ان کی عزت و آبرو اور
ان کے دین و مذہب کا یقیناً خاتمہ تھا.پس بنو قریظہ کسی ایک جرم کے مرتکب نہیں ہوئے بلکہ وہ بے وفائی
اور احسان فراموشی کے مرتکب ہوئے.بدعہدی اور غداری کے مرتکب ہوئے.بغاوت اور اقدام قتل کے
ابو داؤد بحوالہ تلخيص الصحاح جلد اباب سورۃ مائده
Page 703
۶۸۸
مرتکب ہوئے اوران جرموں کا ارتکاب انہوں نے ایسے حالات میں کیا جو ایک جرم کو بھیا نک سے
بھیانک صورت دے سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی غیر متعصب عدالت ان کے مقدمہ میں موجبات رعایت
کا عنصر نہیں پاسکتی.ایسے حالات میں ان کی سزا سوائے اس کے کیا ہو سکتی تھی جو دی گئی.ظاہر ہے کہ امکانی طور پر صرف
تین سزائیں ہی دی جا سکتی تھیں.اوّل مدینہ میں ہی قید یا نظر بندی.دوسرے جلا وطنی جیسا کہ بنو قینقاع
اور بنونضیر کے معاملہ میں ہوا.تیسرے جنگجو آدمیوں
کا قتل اور باقیوں کی قید یا نظر بندی.اب انصاف کے
ساتھ غور کرو کہ اس زمانہ کے حالات کے ماتحت مسلمانوں کے لئے کون سا طریق کھلا تھا.ایک دشمن قوم کا
اپنے شہر میں قید رکھنا اس زمانہ کے لحاظ سے بالکل بیرون از سوال تھا.کیونکہ اوّل تو قید کے ساتھ ہی
قیدیوں کی رہائش اور خوراک کی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی تھی جس کے برداشت کرنے کی ان میں
ہرگز طاقت نہیں تھی.دوسرے اس زمانہ میں کوئی جیل خانے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے اور قیدیوں کے
متعلق یہی دستور تھا کہ وہ فاتح قوم کے آدمیوں میں تقسیم کر دئے جاتے تھے جہاں وہ عملاً بالکل آزا در بہتے
تھے.ایسے حالات میں ایک پرلے درجہ کے معاند اور سازشی گروہ کا مدینہ میں رہنا اپنے اندر نہایت
خطرناک احتمالات رکھتا تھا اور اگر بنو قریظہ پر یہ فیصلہ جاری کیا جاتا تو یقیناً اس کے معنے یہ ہوتے کہ فتنہ
انگیزی اور مفسدہ پردازی اور شرارت اور خفیہ ساز باز کے لئے تو ان کو وہی آزادی حاصل رہتی جو پہلے تھی
البتہ ان کے اخراجات کی ذمہ داری مسلمانوں پر آجاتی یعنی پہلے اگر وہ اپنا کھاتے تھے اور مسلمانوں کا گلا
کاٹتے تھے تو آئندہ وہ کھاتے بھی مسلمانوں کا (جن کے پاس اس وقت اپنے کھانے کے لئے بھی نہیں تھا )
اور گلا بھی مسلمانوں کا کاٹتے اور مسلمانوں کے گھروں میں اور ان کے ساتھ مخلوط ہو کر رہنے سہنے کی وجہ
سے جو دوسرے خطرات ہو سکتے تھے وہ مزید برآں تھے.اندریں حالات میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی عق
یہ رائے رکھ سکتا ہے کہ بنو قریظہ کو یہ سزادی جاسکتی تھی.اب رہی دوسری سزا یعنی جلا وطنی.سو یہ سزا بے شک اس زمانہ کے لحاظ سے دشمن کے شر سے محفوظ
رہنے کے لئے ایک عمدہ طریق سمجھی جاتی تھی مگر بنو نضیر کی جلاوطنی کا تجر بہ بتا تا تھا کہ کم از کم جہاں تک
یہود کا تعلق تھا یہ طریق کسی صورت میں پہلے طریق سے کم خطرناک نہیں تھا.یعنی یہود کو مدینہ سے باہر
نکل جانے کی اجازت دے دینا سوائے اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ عملی اور جنگجو
معاندین اسلام کی تعداد میں اضافہ ہو جاوے بلکہ دشمنان اسلام کی صف میں ایسے لوگ جاملیں جو اپنی خطرناک
شخص
عظمند
Page 704
۶۸۹
اشتعال انگیزی اور معاندانہ پراپیگنڈا اور خفیہ اور سازشی کارروائیوں کی وجہ سے ہر مخالف اسلام تحریک کے
لیڈر بننے کے لئے بے چین تھے.تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ یہود کے سارے
قبائل میں سے بنو قریظہ اپنی
عداوت میں بڑھے ہوئے تھے.پس یقیناً بنو قریظہ کی جلا وطنی اس سے بہت زیادہ خطرات کا موجب
ہو سکتی تھی جو بنونضیر نے غزوہ احزاب کو برپا کر کے مسلمانوں کے لئے پیدا کئے اور اگر مسلمان ایسا کرتے تو
اس زمانہ کے حالات کے ماتحت ان کا یہ فعل ہرگز خود کشی سے کم نہ ہوتا مگر کیا دنیا کے پردے پر کوئی ایسی قوم
ہے جو دشمن کو زندہ رکھنے کے لئے آپ خود کشی پر آمادہ ہوسکتی ہے؟ اگر نہیں تو یقیناً مسلمان بھی اس وجہ سے
زیر الزام نہیں سمجھے جاسکتے کہ انہوں نے بنوقریظہ کو زندہ رکھنے کے لئے خودکشی کیوں نہیں کی.پس یہ ہر دوسرا ئیں ناممکن تھیں اور ان میں سے کسی کو اختیار کرنا اپنے آپ کو یقینی تباہی میں ڈالنا
تھا.اور ان دوسزاؤں کو چھوڑ کر صرف وہی رستہ کھلا تھا جو اختیار کیا گیا.بے شک اپنی ذات میں سعد کا
فیصلہ ایک سخت فیصلہ تھا اور فطرت انسانی بظاہر اس سے ایک صدمہ محسوس کرتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس
کے بغیر کوئی اور راستہ کھلا تھا جسے اختیار کیا جاتا.جب ایک سرجن اپنے کسی بیمار کا جس کے لئے وہ اس قسم کا
اپریشن ضروری خیال کرے ہاتھ کاٹ دیتا ہے یا ٹانگ جدا کر دیتا ہے یا کسی اور عضو کو جسم سے علیحدہ کر دینے
پر مجبور ہو جاتا ہے تو ہر شریف انسان کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا یعنی اگر حالات کی مجبوری
اسے ضروری نہ قرار دیتی تو اچھا تھا مگر حالات کی مجبوری کے سامنے جھکنا پڑتا ہے بلکہ ایسے حالات میں
سرجن کا یہ فعل قابل تعریف سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تھوڑے یا کم قیمتی حصہ کی قربانی سے زیادہ قیمتی چیز کو
بچالیا.اسی طرح بنو قریظہ کے متعلق سعد کا فیصلہ گو اپنی ذات میں سخت تھا مگر وہ حالات کی مجبوری کا ایک
لازمی نتیجہ تھا جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا.یہی وجہ ہے کہ مارگولیس جیسا مؤرخ بھی جو ہرگز اسلام کے
دوستوں میں سے نہیں ہے اس موقع پر اس اعتراف پر مجبور ہوا ہے کہ سعد کا فیصلہ حالات کی مجبوری پر مبنی
تھا جس کے بغیر چارہ نہیں تھا.چنانچہ مسٹر مار گولیس صاحب لکھتے ہیں کہ :
غزوہ احزاب کا حملہ جس کے متعلق محمد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ محض خدائی تصرفات
کے ماتحت پسپا ہوا وہ بنو نضیر ہی کی اشتعال انگیز کوششوں کا نتیجہ تھایا کم از کم یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ
ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور بنو نضیر وہ تھے جنہیں محمد صاحب نے صرف جلا وطن کر دینے پر اکتفا
کی تھی.اب سوال یہ تھا کہ کیا محمد صاحب بنو قریظہ کو بھی جلا وطن کر کے اپنے خلاف اشتعال انگیز
ا زاد المعاد حالات بنو قریظہ
Page 705
کوششیں کرنے والوں کی تعداد اور طاقت میں اضافہ کر دیں؟ دوسری طرف وہ قوم مدینہ میں
بھی نہیں رہنے دی جا سکتی تھی جس نے اس طرح بر ملا طور پر حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا.ان کا
جلا وطن کرنا غیر محفوظ تھا مگر ان کا مدینہ میں رہنا بھی کم خطرناک نہ تھا.پس اس فیصلہ کے بغیر
چارہ نہ تھا کہ ان کے قتل کا حکم دیا جاتا.“
پھر یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ مد نظر رکھنی چاہئے کہ بنوقریظہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف
حلیف اور معاہد ہی نہیں تھے بلکہ وہ اپنے ابتدائی معاہدہ کی رو سے مدینہ میں آپ کی حکومت کو تسلیم کر چکے
تھے یا کم از کم آپ کی سوورینیٹی (sovereignty) کو انہوں نے قبول کیا تھا.پس ان کی حیثیت صرف
ایک غدار حلیف یا معمولی دشمن کی نہیں تھی بلکہ وہ یقیناً باغی بھی تھے اور باغی بھی نہایت خطرناک قسم کے
باغی اور باغی کی سزا خصوصاً جنگ کے ایام میں سوائے قتل کے کوئی اور نہیں سمجھی گئی.اگر باغی کو بھی انتہائی سزا
نہ دی جاوے تو نظام حکومت بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور شریر اور مفسدہ پرداز لوگوں کو ایسی جرات حاصل
ہو جاتی ہے جو امن عامہ اور رفاہ عام کے لئے سخت مہلک ثابت ہوتی ہے اور یقیناً ایسے حالات میں باغی
پر رحم کرنا دراصل ملک پر اور ملک کے امن پسند لوگوں پر ظلم کے ہم معنی ہوتا ہے.چنانچہ تمام متمدن حکومتیں
اس وقت تک ایسے باغیوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت قتل کی سزا دیتی چلی آئی ہیں اور کسی عقلمند انسان نے
کبھی ان پر اعتراض نہیں کیا.پس سعد کا فیصلہ بالکل منصفانہ اور عدل وانصاف کے قواعد کے بالکل مطابق
تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ اپنے عہد کے اس فیصلہ کے متعلق رحم کے پہلو کو کام میں نہیں لا سکتے تھے
سوائے افراد کے اور اس کے لئے آپ نے ہر ممکن کوشش کی مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے اس شرم سے کہ
انہوں نے آپ کو حج ماننے سے انکار کر دیا تھا آپ کی طرف رحم کی اپیل کی صورت میں زیادہ رجوع نہیں کیا
اور ظاہر ہے کہ بغیر اپیل ہونے کے آپ رحم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ جو باغی اپنے جرم پر ندامت کا اظہار بھی
نہیں کرتا اسے خود بخود چھوڑ دینا سیاسی طور پر نہایت خطرناک نتائج پیدا کرسکتا ہے.ایک اور بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ جو معاہدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان
ابتدا میں ہوا تھا اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر یہود کے متعلق کوئی امر قابل تصفیہ پیدا
ہوگا تو اس کا فیصلہ خود انہیں کی شریعت کے ماتحت کیا جائے گا.چنانچہ تاریخ سے پتا لگتا ہے کہ اس معاہدہ
کے ماتحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہود کے متعلق شریعت موسوی کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے.: محمد مصنفه مارگولیس صفحه ۳۳۳
Page 706
۶۹۱
اب ہم تو رات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں اس قسم کے جرم کی سزا جس کے مرتکب بنوقریظہ ہوئے بعینہ وہی
لکھی ہوئی پاتے ہیں جو سعد بن معاذ نے بنوقریظہ پر جاری کی.چنانچہ بائبل میں یہ خدائی حکم درج ہے کہ :
اور جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لئے آپہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام
کر.تب یوں ہوگا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور اور دروازہ تیرے لئے کھول دے تو
ساری خلق جو اس شہر میں پائی جاوے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی اور اگر وہ
تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کر اور جب خداوند تیرا خدا اسے
تیرے قبضے میں کر دیوے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر مگر عورتوں اور
لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا لوٹ اپنے لئے لے لے
یہودی شریعت کا یہ حکم محض ایک کاغذی حکم نہیں تھا جس پر کبھی عمل نہ کیا گیا ہو بلکہ بنواسرائیل کا
ہمیشہ اسی پر عمل رہا ہے اور یہودی قضیئے ہمیشہ اسی اصل کے ماتحت تصفیہ پاتے رہے ہیں.چنانچہ
مثال کے طور پر ملاحظہ ہو :.” اور انہوں نے (یعنی بنو اسرائیل نے ) مدیا نیوں سے لڑائی کی جیسا خداوند نے موسیٰ کو
فرمایا تھا اور سارے مردوں
کو قتل کیا اور انہوں نے ان مقتولوں کے سواعوتی اور رقم اور
صور اور حور اور ربع کو جو مدیان کے پانچ بادشاہ تھے جان سے مارا اور باعود کے بیٹے بلعام کو
بھی تلوار سے قتل کیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان
کے مواشی اور بھیڑ بکری اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا.اور انہوں نے سارا مال غنیمت
اور سارے اسیر انسان اور حیوان لئے اور وے قیدی اور غنیمت اور لوٹ موسیٰ اور الیعزر کا ہن
اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس خیمہ گاہ میں موآب کے میدانوں میں سیر دن کے
کنارے جوبر بجو کے مقابل ہے، لائے..حضرت مسیح ناصری کو ( جو وہ بھی بنواسرائیل میں سے ہی تھے ) گوا اپنی زندگی میں حکومت نصیب نہیں
ہوئی اور نہ جنگ وجدال کے موقعے پیش آئے جن میں ان کا طریق عمل ظاہر ہوسکتا مگر ان کے بعض فقروں
سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریر اور بد باطن دشمنوں کے متعلق ان کے کیا خیالات تھے.چنانچہ اپنے دشمنوں
2: استثناء باب ۲۰ آیت ۱۰ تا ۱۵
: گنتی باب ۳۱.آیت ۷ تا ۱۲
Page 707
۶۹۲
کو مخاطب کر کے حضرت مسیح فرماتے ہیں :.”اے سانپو! سانیوں کے بچو! تم جہنم کی سزا سے کیونکر بچو گے ؟
یعنی اے لوگو! تم زہریلے سانپوں کی طرح بن کر ہلاک کئے جانے کے قابل ہو گئے ہولیکن مجھے.طاقت حاصل نہیں ہے کہ تمہیں سزا دوں مگر تم خدا سے ڈرو اور جہنم کی سزا کا ہی خیال کر کے اپنی بد کردار یوں
اور شرارتوں سے باز آجاؤ.غالباً یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مسیح کے متبعین کو دنیا میں طاقت حاصل ہوئی تو
انہوں نے حضرت مسیح کی اس تعلیم کے ماتحت کہ شریر اور بد کردار دشمن سانپوں اور بچھوؤں کی طرح ہلاک
کئے جانے کے قابل ہے، جسے بھی بد کردار اور شریر سمجھا اور اپنے ارادوں میں رخنہ انداز پایا اسے ہلاک کرنے
میں دریغ نہیں کیا.چنانچہ مسیحی اقوام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے.خلاصہ کلام یہ کہ سعد کا فیصلہ گواپنی ذات میں سخت سمجھا جاوے مگر وہ ہرگز عدل وانصاف کے خلاف
نہیں تھا اور یقیناً یہود کے جرم کی نوعیت اور مسلمانوں کی حفاظت کا سوال دونوں اسی کے مقتضی تھے کہ
یہی فیصلہ ہوتا اور پھر یہ فیصلہ بھی یہودی شریعت کے عین مطابق تھا بلکہ اس ابتدائی معاہدہ کے لحاظ سے
ضروری تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ اس کی رو سے مسلمان اس بات کے پابند تھے کہ یہود کے متعلق انہی کی
شریعت کے مطابق فیصلہ کریں.مگر جو کچھ بھی تھا یہ فیصلہ سعد بن معاذ کا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا نہیں تھا.اور سعدؓ پر ہی اس کی پہلی اور آخری ذمہ داری عائد ہوتی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا تعلق بحیثیت صدر حکومت کے اس سے صرف اس قدر تھا کہ آپ اس فیصلہ کو اپنی حکومت کے
انتظام کے ماتحت جاری فرما دیں.اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری فرمایا
جو موجودہ زمانہ کی مہذب سے مہذب اور رحم دل سے رحم دل حکومت کے لئے بھی ایک بہترین نمونہ
سمجھا جاسکتا ہے.انصار کے رئیس اعظم کی وفات اور نعماء جنت کی حقیقت حضرت سعد بن معاذ رئیس
قبیلہ اوس کی کلائی میں جو زخم
غزوہ خندق کے موقع پر آیا تھا وہ با وجود بہت علاج معالجہ کے اچھا ہونے میں نہیں آتا تھا اور مندمل ہو ہو کر
پھر کھل کھل جاتا تھا.چونکہ وہ ایک بہت مخلص صحابی تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیمارداری کا
خاص خیال تھا اس لئے آپ نے غزوہ خندق کی واپسی پر ان کے متعلق ہدایت فرمائی تھی کہ انہیں مسجد کے
متی باب ۲۳ آیت ۳۳
Page 708
۶۹۳
صحن میں ایک خیمہ میں رکھا جاوے تا آپ آسانی کے ساتھ ان کی تیمار داری فرما سکیں.چنانچہ انہیں ایک
مسلمان عورت رفیدہ نامی کے خیمہ میں رکھا گیا جو بیماروں کی تیمارداری اور نرسنگ میں مہارت رکھتی تھی اور
عموما مسجد کے صحن میں خیمہ لگا کر مسلمان زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی یا مگر باوجود اس غیر معمولی توجہ کے
سعد کی حالت رو به اصلاح نہ ہوئی اور اسی دوران میں بنو قریظہ کا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے سعد کو
غیر معمولی مشقت اور کوفت برداشت کرنی پڑی اور ان کی کمزوری بہت بڑھ گئی.انہی ایام میں ایک رات
سعد نے نہایت گریہ وزاری سے یہ دعا کی کہ اے میرے مولا تو جانتا ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش
کس طرح بھری ہوئی ہے کہ اس قوم کے مقابل میں تیرے دین کی حفاظت کے لئے جہاد کروں جس نے
تیرے رسول کی تکذیب کی اور اسے اس کے وطن سے نکال دیا.اے میرے آقا! میرے خیال میں اب
ہمارے اور قریش کے درمیان لڑائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن اگر تیرے علم میں کوئی جنگ ابھی باقی ہے
تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں تیرے رستے میں ان کے ساتھ جہاد کروں لیکن اگر ان کے ساتھ ہماری
جنگ ختم ہو چکی ہے تو مجھے اب زندگی کی تمنا نہیں ہے مجھے اس شہادت کی موت مرنے دے.“ لکھا ہے کہ
اسی رات سعد کا زخم کھل گیا اور اس قدر خون بہا کہ خیمے سے باہر نکل آیا اور لوگ گھبرا کر خیمہ کے اندر ہو گئے
تو سعد کی حالت دگر گوں تھی آخر اسی حالت میں سعد نے جان دے دی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور واقعی اس وقت کے حالات کے
ماتحت سعد کی وفات مسلمانوں کے لئے ایک نا قابل تلافی نقصان تھی.سعد کو انصار میں قریب قریب وہی
حیثیت حاصل تھی جو مہاجرین میں ابو بکر صدیق کو حاصل تھی.اخلاص میں، قربانی میں ،خدمت اسلام میں،
عشق رسول میں یہ شخص ایسا بلند مرتبہ رکھتا تھا جو کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا کرتا ہے اور اس کے ہر حرکت وسکون
سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسلام اور بانی اسلام کی محبت اس کی روح کی غذا ہے اور بوجہ اس کے کہ وہ اپنے قبیلہ
کا رئیس تھا اس کا نمونہ انصار میں ایک نہایت گہرا عملی اثر رکھتا تھا.ایسے قابل روحانی فرزند کی وفات پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ ایک فطری امر تھا مگر آپ نے کامل صبر سے کام لیا اور خدائی مشیت کے
سامنے تسلیم ورضا کا سر جھکا دیا.جب سعد کا جنازہ اٹھا تو سعد کی بوڑھی والدہ نے بتقاضائے محبت کسی قدر بلند آواز سے ان کا نوحہ
کیا اور اس نوحہ میں زمانہ کے دستور کے مطابق سعد کی بعض خوبیاں بیان کیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
بخاری کتاب المغازی باب مَرْجَعُ النَّتِي مِنَ الْأَحْزَابِ
طبری وابن سعد
Page 709
۶۹۴
وو
نے اس نوحہ کی آواز سنی تو گو آپ نے اصولاً نوحہ کرنے کو پسند نہیں کیا مگر فرمایا کہ نوحہ کرنے والیاں بہت
جھوٹ بولا کرتی ہیں لیکن اس وقت سعد کی ماں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے یعنی جو خو بیاں سعد میں
بیان کی گئی ہیں وہ سب درست ہیں.یہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور
دفنانے کے لئے خود ساتھ تشریف لے گئے اور قبر کی تیاری تک وہیں ٹھہرے رہے اور آخر وہاں سے دعا
کرنے کے بعد تشریف لائے.۲
غالبا اسی دوران میں کسی موقع پر آپ نے فرمایا.اهْتَزَّ عَرُشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ = یعنی
سعد کی موت پر خدائے رحمان کا عرش جھومنے لگ گیا ہے.یعنی عالم آخرت میں خدا کی رحمت نے خوشی
کے ساتھ سعد کی روح کا استقبال کیا ہے.ایک عرصہ کے بعد جب آپ کو کسی جگہ سے کچھ ریشمی پار چات
ہدیۂ آئے تو بعض صحابہ نے انہیں دیکھ کر ان کی نرمی اور ملائمت کا بڑے تعجب کے ساتھ ذکر کیا اور اسے ایک
غیر معمولی چیز جانا.آپ نے فرمایا ” کیا تم ان کی نرمی پر تعجب کرتے ہو.خدا کی قسم جنت میں سعد کی چادریں
ان سے بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ اچھی ہیں.“ ہے
نعمائے جنت کی حقیقت آپ کا یہ کلام ایک استعارے کے رنگ میں تھا جس میں سعد کے اس
راحت کے مقام کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا جو انہیں جنت میں حاصل
ہوا تھا.ورنہ جیسا کہ قرآن شریف اور احادیث سے اصولی طور پر پتا لگتا ہے جنت کی نعمتوں کا اس دنیا کی
نعمتوں پر قیاس نہیں ہوسکتا اور نہ جنت کی نعمتیں ہماری اصطلاح کے لحاظ سے مادی کہلا سکتی ہیں اور حق یہی
ہے کہ جو الفاظ قرآن وحدیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں صرف استعارہ اور تشبیہ کے طور پر نعمتوں
کے کمال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے.چنانچہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ اصولی طور پر فرماتا ہے.فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 20 یعنی کوئی
شخص نہیں سمجھ سکتا کہ نیک لوگوں کے اعمال کے بدلے میں ان کے لئے جنت میں کسی قسم کا آنکھ کی ٹھنڈک کا
سامان مہیا کیا گیا ہے.اور اس کی تفسیر میں حدیث میں آتا ہے لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا
خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ - 3 یعنی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کبھی کسی انسان کی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا
ل : زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۴۱
بخاری ابواب مناقب انصار
: سورة السجدة: ۱۸
زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۴۱
بخاری باب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ
بخاری کتاب التفسير سورة تنزيل السجدة
Page 710
۶۹۵
اور کبھی کسی انسان کے کان نے انہیں نہیں سنا اور نہ ان کا تصور کبھی کسی بشر کے دل میں گزرا ہے.‘ پس
لا ز ماماننا پڑے گا کہ جنت کی نعمتیں وہ نعمتیں نہیں جو ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں.یعنی جنت کے پھل وہ پھل
نہیں جو ہم اس دنیا میں کھاتے ہیں اور جنت کے دودھ اور شہد وہ دودھ اور شہد نہیں جو ہم اس دنیا میں پیتے
ہیں اور جنت کی حوریں وہ حوریں نہیں جو ہم اس دنیا میں خوبصورت عورت کے معنوں میں سمجھتے ہیں بلکہ وہ
کچھ اور ہی چیزیں ہیں جن کو بطریق استعارہ اس دنیا کی چیزوں کا نام دے دیا گیا ہے مگر جن کا وہم و تصور
بھی ہمارے خیال میں نہیں آسکتا.لیکن اس قدر بہر حال یقینی ہے کہ جنت کی سب نعمتیں خواہ وہ انسانی روح
کے واسطے ہوں یا جسم کے لئے وہ خالص پاکیزگی اور طہارت پر مبنی ہیں اور ہر قسم کی بدی اور ناپاکی کے عنصر
سے کلیتا پاک ہیں کیونکہ قرآن شریف فرماتا ہے لَا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيم ا یعنی ” جنت وہ مقام ہے کہ
اس میں کوئی عنصر بے ہودگی اور بدی اور ناپاکی کا نہیں ہو گا.“
۵ ہجری کے بعض متفرق واقعات اس سال میں بعض متفرق واقعات بھی ہوئے جن کی معین
تاریخ روایات میں مذکور نہیں ہوئی.ان میں سے ایک واقعہ
ایک زلزلہ کا آنا ہے.جب یہ دھکا مدینہ میں محسوس ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت
فرمائی کہ یہ قدرت کے واقعات ہیں جن سے ایک مومن کو نصیحت حاصل کرنی چاہئے اور اللہ تعالیٰ
بعض اوقات اس قسم کے واقعات لوگوں کے بیدار کرنے کے لئے پیدا کر دیتا ہے اور ان کو ہوشیار و چوکس
رکھنا چاہتا ہے.بعض روایات کے مطابق اسی سال حج فرض ہوا لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ روایات درست
نہیں ہیں بلکہ حج کی باقاعدہ مشروعیت کا زمانہ بعد کا ہے گوجیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے عید اضحی جو
حج کے ساتھ لازم وملزوم کے طور پر ہے ۲ ہجری میں ہی مشروع ہوگئی تھی اور صحیح روایات سے یہ بھی پتا
چلتا ہے کہ مسلمان شروع سے ہی خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور نفل وغیرہ کے طریق پر کعبتہ اللہ
کا طواف بھی موقع پا کر کرتے رہتے تھے مگر فریضہ حج کی باقاعدہ اور بالتفصیل مشروعیت غالباً بعد میں ہوئی
تھی کے اس لئے ہم اس بحث کو اس جگہ ترک کرتے ہیں.اسی سال یعنی ۵ ہجری میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے پر سے گر گئے اور آپ کی پنڈلی اور ران وغیرہ پر چوٹیں آئیں جس کی وجہ سے
۲: خمیس جلد اصفحه ۵۶۵
: سورۃ طور : ۲۴
س زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۴۳.نیز زاد المعاد جلد اصفحه ۱۸۰
Page 711
۶۹۶
آپ پانچ دن بیٹھ کر نماز ادا فرماتے رہے.فنون سپاہ گری کی طرف آپ
کی توجہ اس سال آپ نے جنگی ضروریات کے ماتحت بعض
گھڑ دوڑیں کروائیں ہے اور ویسے یہ تحریک تو آپ
صحابہ میں ہمیشہ فرماتے رہتے تھے کہ وہ گھوڑے رکھیں اور سواری کے فن میں کمال پیدا کریں اور جہاد کی
غرض وغایت کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اسے ایک بڑا کار ثواب خیال فرماتے تھے.تے چنانچہ جن صحابہ کو
توفیق تھی وہ خاص شوق کے ساتھ گھوڑے پالتے تھے اور ایک روایت میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام
گھوڑوں کی کدائی کی مشق بھی کیا کرتے تھے." اسی طرح آپ اونٹوں کی دوڑ بھی کروایا کرتے تھے
چنانچہ خود آپ کی اپنی ایک اونٹنی تھی جو عموما سب سے آگے رہتی تھی.دراصل آپ
کا یہ عام طریق تھا کہ آپ جسمانی ورزش اور تحصیل فنون سپاہ گری کی طرف اپنے صحابہ کو
بہت توجہ دلاتے رہتے تھے اور بعض اوقات ان میں جوش پیدا کرنے کے لئے خود بھی ایسے موقعوں پر
حصہ لیتے تھے.چنانچہ بعض اوقات آپ نے اپنے سامنے تیراندازی اور تلوار اور نیزے کے کرتبوں کے
مقابلے کرائے.آپ یہ بھی تحریک فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو چست ہو کر اور تیز تیز چلنا چاہئے.تاکہ
دشمن پر ان کی مضبوطی اور چستی کا رعب پڑے اور خود بھی ان میں چستی کا احساس پیدا ہو.جنگی ضروریات
کے لئے بعض صحابہ تیز دوڑنے کی بھی مشق کیا کرتے تھے.چنانچہ اس معاملہ میں ایک صحابی سلمہ بن اکوع
خاص طور پر ماہر تھے حتی کہ بعض روایات سے پتا لگتا ہے کہ بعض اوقات وہ گھوڑوں سے بھی آگے نکل
جاتے تھے.دو ایک دفعہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑنے
کا مقابلہ کیا تھا اور گو یہ خوش مزاجی کے طریق پر ہو مگر اس سے اس زندہ اور چست روح کے اندازہ
ل خمیس جلد اصفحه ۵۶۵ نیز موطا باب صلوۃ الامام وَهُوَ جَالِسٌ -
: خمیس جلد اصفحه ۵۶۵ - نیز بخاری کتاب الجہاد باب غایۃ السبق الخیل
بخاری کتاب الجہاد باب من احتبس فرساً
بخاری کتاب الجہاد باب ناقتہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بخاری کتاب الجہاد باب التحريض على الرمی و باب الدرق
کے بخاری کتاب المغازی باب عمرة القضاء
ابوداؤ د باب السبق
خمیس جلد اصفحه ۵۶۵
: اصابه حالات سلمہ بن اکوع
Page 712
۶۹۷
کرنے کا موقع ملتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی میں کام کرتی تھی اور جس سے ان کی
مستورات بھی خالی نہیں تھیں.اسلامی قانون شادی و طلاق شادی اور طلاق وغیرہ کے مسائل کے متعلق بھی بہت سے اسلامی
احکام اسی سال نازل ہوئے.اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
اس موقع پر ایک مختصر سا خاکہ شادی اور طلاق کے مسائل کے متعلق اسلامی تعلیم کا پیش کر دیا جاوے.وسب سے پہلے تو یہ جاننا چاہئے کہ اسلام سے قبل عربوں میں کوئی خاص قانون شادی وطلاق مقرر
نہیں تھا بلکہ محض ایک رسم یا طریق عمل کی صورت تھی اور اس کی پابندی بھی ہر شخص کی اپنی مرضی پر موقوف تھی
اور اسی لئے ملک کے مختلف حصوں اور مختلف قبائل میں یہ طریق عمل مختلف صورتیں رکھتا تھا.عام طور پر یہ سمجھنا چاہئے کہ عرب میں جائز و نا جائز رشتوں میں زیادہ حد بندی نہیں تھی.حتی کہ سوتیلی
ماں تک سے شادی کرنے میں پر ہیز نہیں تھا لے قریبی رشتہ دار کی بیوہ پر بغیر اس کی مرضی کے زبردستی قبضہ
کر لینے کی رسم بھی پائی جاتی تھی.یہ نکاح کے طریق مختلف تھے اور ان میں سے چار زیادہ شائع ومتعارف
تھے.ان میں سے ایک تو یہی رسمی نکاح تھا جو بعد میں زیادہ پاک وصاف ہوکر اسلام میں قائم ہوالیکن باقی
تین ایسے گندے اور ناپاک تھے کہ ان کے ذکر تک سے انسانی طبیعت رکتی ہے..تعدد ازدواج کی کوئی
حد بندی نہیں
تھی بلکہ بیویوں کی تعداد ہر شخص کی ذاتی ضرورت.دولت اور شوق پر منحصر تھی ہے بیویوں
کے درمیان عدل و انصاف کا کوئی ضابطہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کے متعلق خاوند پر کوئی پابندی تھی.مرد کے
عورت پر اور عورت کے مرد پر کوئی مقررہ حقوق نہیں تھے بلکہ سارا دارو مدار مرد کی مرضی پر تھا.طلاق کا کوئی
قانون نہیں تھا.مرد جب اور جس طرح چاہتا تھا عورت کو طلاق دے کر الگ کر دیتا تھا.اگر مرد کی
مرضی نہ ہو تو عورت کے لئے طلاق حاصل کرنے کا کوئی رستہ نہیں تھا.طلاق کے بعد بھی جابر لوگ اپنی
مطلقہ عورت پر حکومت رکھتے تھے اور اسے دوسری جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے.عدت کا
قانون بھی کوئی نہیں تھا بلکہ ادھر جدائی ہوتی تھی اور ادھر عورت دوسرے شخص کے ساتھ شادی کے لئے
قرآن شریف سورة النساء : ۲۳
بخاری کتاب النکاح باب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي
: سورۃ النساء : ۲۰
ترندی ابواب النکاح باب مَا جَاءَ فِى الرَّجُل يَسْلِمُ وَعِندَهُ عَشَرُ نِسْوَةٍ
۵: سورة البقرة : ۲۳۳
Page 713
۶۹۸
آزاد سمجھی جاتی تھی.الغرض شادی و طلاق کے معاملہ میں عرب میں کوئی قانون نہیں تھا بلکہ سارا
دارو مدار مرد کی مرضی پر تھا.اور مرد عموماً اپنی بیویوں کے ساتھ نہایت جابرانہ سلوک کرتے تھے
اور عورت کے لئے کوئی دادرسی کی جگہ نہیں تھی.اسلام آیا تو اس نے گویا ایک نیا عالم پیدا کر دیا اور محض
انتظامی فرق کے سوا کہ جو لا بدی تھا اصولاً عورت اور مرد کے مساویانہ حقوق تسلیم کئے ہے اور ان حقوق کی
حفاظت و نگہداشت کا کام مرد پر نہیں چھوڑا بلکہ حکومت کے ہاتھ میں دیا اور حکومت کا یہ فرض مقرر کیا کہ
وہ خاوند و بیوی کے حقوق میں ایک دوسرے کی دست درازی کورو کے اور خصوصاً ضعیف طبقہ نساء کی
حفاظت کرے.اور دوسری طرف اسلام نے اپنے روحانی اور اخلاقی اثر کے ماتحت مردوں کو یہ پر زور
سفارش کی کہ وہ عورتوں کے ساتھ نہ صرف عدل و انصاف بلکہ شفقت واحسان کا معاملہ کریں اور اس
معاملہ میں اسلام نے اتنا زور دیا کہ بعض صحابہ میں یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ اسلام نے تو گویا عورت کو
آزاد کر دیا ہے..اسلامی قانون شادی و طلاق کا اصل الاصول یہ ہے کہ نکاح مرد وعورت کے درمیان ایک سول
معاہدہ کا رنگ رکھتا ہے.جسے گو عام معاہدات کی نسبت بہت زیادہ محبت اور وفاداری اور تقدس اور دوام
کا عنصر دیا گیا ہے.مگر انتہائی حالات میں وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے.اور اسی ٹوٹنے کا نام اسلامی اصطلاح
میں طلاق یا خلع یا فسخ نکاح ہے.یہ سول معاہدہ کس طرح قائم ہوسکتا اور کس طرح ٹوٹ سکتا ہے اس کے
-1
متعلق اسلامی قانون کا ڈھانچہ حسب ذیل ہے.پہلے ہم قانون شادی کو لیتے ہیں.ا.نکاح کرنا اسلام میں ہر اس مسلمان پر جو اس کی طاقت رکھتا ہو فرض ہے اور تبتل سے منع کیا گیا ہے.نکاح کی اغراض تعدد ازدواج کی بحث میں دوسری جگہ مفصل بیان کی جاچکی ہیں اس جگہ اعادہ
موطا امام مالک کتاب النکاح باب جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ : سورة البقرة : ۲۲۹
-۲
مسلم کتاب النکاح باب في الايلاء وابوداؤ د كتاب النکاح باب فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ
سورة بقرة : ۲۳۳ تا ۲۳۸ وسورة نساء ۲۱ ۲۲ نیز بخاری کتاب النکاح باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
بخاری کتاب النکاح باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
سورۃ طلاق: ۳۲ وابوداؤ د کتاب الطلاق
ك سورة نساء :۲ و سورة نور : ۳۳ ۳۴ و بخارى كتاب النكاح بَابُ الترغيب في النكاح وباب مَنِ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمُ الْبَاءَةَ وَ بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبَتْلِ
Page 714
۶۹۹
کی ضرورت نہیں ہے.جن جگہوں میں رشتہ منع ہے ان کا اسلام نے صراحت و تعیین کے ساتھ ذکر کر دیا ہے باقی سب کے
ساتھ نکاح ہوسکتا ہے.کوئی قومی یا نسلی حد بندی نہیں ہے.ممنوع رشتے اصولاً یہ ہیں.باپ کی
بیوی ، ماں، رضاعی ماں، بیٹی، بیوی کی بیٹی، بہن، رضاعی بہن، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، ساس،
بہو، ہر خاوند والی عورت ، اور دو بہنوں کا ایک وقت میں جمع کرنا ہے اس حکم کی مزید تشریح حدیث میں
کر دی گئی ہے.-۴- نکاح چونکہ مرد و عورت کے ایک معاہدہ کا نام ہے اور انہوں نے ہی اسے نباہنا ہوتا ہے اس لئے نکاح
میں فریقین کی رضا مندی ضروری ہے.یعنی لڑکا اور لڑکی یا مرد و عورت دونوں اس تعلق کے قائم کرنے پر
رضامند ہونے چاہئیں اور ان کی رضامندی کے بغیر یہ رشتہ قائم نہیں ہوسکتا ہے
-
باوجود پردہ کی حد بندیوں کے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی تحریک کرتا ہے کہ نکاح
سے پہلے مرد و عورت ایک دوسرے پر نظر ڈال لیں تاکہ شکل وغیرہ کا سوال بعد میں موجب خلش نہ بنے.اسلام میں نکاح اعلان کے ساتھ علی رؤس الا شہاد ہونا ضروری ہے اور خفیہ نکاح کی اجازت نہیں
ہے.اسی اعلان کی غرض سے اسلام میں یہ طریق مقرر کیا گیا ہے کہ جب خاوند بیوی اکٹھے ہوں تو اس
خوشی میں خاوند ایک دعوت دے جس میں حسب توفیق اعزہ واحباب اور ہمسائے وغیرہ بلائے جائیں.-Y
دیکھو کتاب ہذا بحث تعد دازدواج واقعات ۲ھ
سورة نساء : ۲۳ تا ۲۶
بخاری کتاب النکاح ابواب ۲۱ تا ۲۸ نیز دیکھوزادالمعاد فصول متعلقہ
سورۃ نساء : ۴۰۲ و ۲۰، ۲۱.نیز بخاری کتاب النکاح باب لَا يَنكِحُ الحَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَ الشَّيْبَ
الابرِضَاءِ هَا مسلم كتاب النکاح باب اِسْتِيذَانُ الشَّيْبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالبِكْرِ بِالْسَكُوْتِ
۵ : سورة نساء : ۴۰۲ نیز بخاری کتاب النکاح باب النَّظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزويج وترمذی ابواب النکاح باب
مَا جَاءَ فِي النَّظُرِ إِلَى الْمَخْطُوبَةِ
ترمذی ابواب النکاح باب مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ و موطا امام مالک کتاب النکاح باب جَامِعٌ مَا لَا يَجُوزُ
مِنَ النِّكَاحِ
Page 715
اس دعوت کو اصطلاحی طور پر ولیمہ کہتے ہیں..ے.اگر کسی خاص مصلحت کے ماتحت کسی لڑکے یا لڑکی کا ولی یعنی گارڈین اس کے بچپن کی حالت میں ہی
یعنی اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے.کیونکہ بعض اوقات استثنائی
صورتوں میں خاص مصالح کے ماتحت ایسا کرنے کی ضروت پیش آسکتی ہے جس کے لئے قانونی طور پر
دروازہ کھلا رہنا چاہئے مگر ایسی صورت میں لڑکے کو تو حق ہے ہی ، لڑکی کو بھی لازماً بالغ ہونے پر حاکم
کے ذریعہ اس رشتہ کے منقطع کرنے کا حق ہوگا اور اس کی رضا مندی کے بغیر یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا.اس حق کو اسلامی اصطلاح میں خیار البلوغ کہتے ہیں مگر یہ خیال رہے کہ ہم نے جو یہ لکھا ہے کہ استثنائی
حالات میں نا بالغی کے زمانہ میں بھی رشتہ ہو سکتا ہے اس سے مراد صرف عقد نکاح ہے.زنا شوئی کے
تعلقات مراد نہیں کیونکہ زنا شوئی کے تعلق کے لئے ہر دو کا بالغ ہونا ضروری ہے.- گونکاح کے عقد میں اصل رضا مندی فریقین کی ہے اور ان کی رضامندی کے بغیر نکاح قائم نہیں رہ
سکتا اور اگر کسی خاص مصلحت سے بچپن میں نکاح ہو بھی جاوے تو نارضامندی کی صورت میں بالغ ہونے پر
وہ قائم نہیں رہ سکتا لیکن چونکہ لڑکی اور خصوصاً کنواری لڑکی طبعاً زیادہ سادہ مزاج اور بھولی ہوتی ہے اور
دنیا کا تجربہ بھی اسے نسبتا کم ہوتا ہے اور وہ ان باتوں سے بھی زیادہ آگاہ نہیں ہوتی جن پر ابلی زندگی کی
حقیقی خوشی کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور پھر فطر تا عورت کے اندر قلبی جذبات کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے جس کی
وجہ سے بسا اوقات جذ بہ عقل مستور ہو جاتا ہے اس لئے اسے کسی غلط راستہ پر پڑنے اور چالاک اور شاطر
مردوں کے دھوکے سے بچانے کے لئے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جب کسی کنواری لڑکی کے رشتہ کا سوال ہو تو
اس کا باپ یا باپ نہ ہو تو کوئی اور قریبی رشتہ دار بطور ولی کے اس کے ساتھ رہے اور اس کے مشورہ کے بغیر
بخاری کتاب النکاح از باب الْوَلِيمَةُ حَقٌّ تَابَابِ إِجَابَةُ الدَّاعِي فِي الْعِرْسِ
: سورة طلاق : ۵ و بخاری کتاب النکاح بَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِغَارِ
سے : اس حق کا اصل الاصول تو قرآن شریف میں ہے جہاں یہ تصریح کی گئی ہے کہ نکاح میں عورت اپنے خاوند سے ایک
پختہ عہد لیتی ہے دیکھو سورۃ نساء : ۲۰ تا ۲۲ اور یہ منشاء پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ بچپن کی شادی کی صورت میں لڑکی بالغ
ہونے پر عقد نکاح کے قائم رکھنے یا ضح کرنے کا حق نہ ہو.نیز دیکھو ترمذی ابواب النکاح باب مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ
الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزويج
: سورة بقرة : ۲۲۴ نیز ترندی تفسیر سورۃ زیر آیت نِسَاءُ كُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ روایت ابن عباس
Page 716
2 +1
رشتہ قائم نہ ہو یا لیکن اگر لڑ کی اور ولی میں اختلاف ہو جاوے تو ترجیح لڑکی کی رائے کو دی جائے گی ہے
مگر اس صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ اس اختلاف کو حاکم کے نوٹس میں لایا جاوے تا کہ اگر لڑ کی کسی
دھو کے کا شکار ہورہی ہو تو اس کا سد باب کیا جا سکے کے بیوہ عورت چونکہ کنواری کی نسبت شادی کے اور پنچ پیچ
سے بہت واقف ہو چکی ہوتی ہے اور ان امور کو سمجھ چکی ہوتی ہے جس پر اہلی تعلقات بہترین صورت میں
چل سکتے ہیں اس لئے اس کے معاملہ میں گوولی کا ساتھ رہنا پسندیدہ ہے مگر ولی کی رضامندی ضروری نہیں
ہے بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے فیصلہ کر سکتی ہے.یہ مسئلہ ولایت جس کا عصر تو کم و بیش اکثر مذاہب میں پایا جاتا ہے مگر جسے اسلام نے ایک معین اور
تفصیلی قانون کی صورت دے دی ہے ایک نہایت ہی مفید اور بابرکت نظام ہے کیونکہ اس سے لڑکیوں
کے نکاح کے معاملہ میں بہت سے دھوکوں کا سدباب ہو جاتا ہے اور شریر اور شاطر لوگ سادہ طبع لڑکیوں
کو سبز باغ دکھا کر اپنے دام تزویر میں پھنسانے کا موقع نہیں پاتے.مغربی ممالک میں جہاں آج کل
لڑکیوں کو نکاح کے معاملہ میں بہت زیادہ آزادی حاصل ہے وہاں اس قسم کے واقعات نہایت کثرت کے
ساتھ ہوتے رہتے ہیں کہ شاطر لوگ بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنی چرب زبانی اور شہوانی محبت کے مظاہروں
سے متاثر کر کے ان کے گارڈینوں کی مرضی اور اطلاع کے بغیر ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں اور جب
وہ ان کے دام میں آجاتی ہیں تو پھر دھو کے کا چولہ اترنا شروع ہو جاتا ہے اور شہوانی محبت بھی آہستہ آہستہ
سرد پڑنے لگ جاتی ہے اور زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ وہ گھر جس کے اندر ان لڑکیوں نے جنت سمجھ کر
قدم رکھا تھا ان کے لئے ایک دوزخ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ابتداء بے التفاتی اور پھر بے اتفاقی اور
پھر لڑائی اور اس کے بعد جدائی اور بالآخر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے.علاوہ ازیں اس ولایت کے انتظام میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس طرح نکاح کی بنیاد صرف
لے ابوداؤ د کتاب النکاح باب فی الولی و ترمندی ابواب النکاح باب مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
: بخاری کتاب النکاح باب لا يَنْكِحُ الابُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَ الشَّيْبَ إِلَّا بِرِضَاءِ هَا - نيز ابوداؤ د كتاب النكاح
باب فِي الْبِكْرِيُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأْمِرُهَا
ترمذی ابواب النکاح باب مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ الأبوَلِي وابوداو و كتاب النکاح باب فِي الْوَلِي
: مسلم کتاب النکاح باب اِسْتِدَانُ الشَّيْبِ فِى النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس - نیز ابوداؤ د کتاب النکاح
باب في الثيب
Page 717
۷۰۲
جذبات پر قائم نہیں ہوتی بلکہ دوسرے امور بھی جو رشتہ نکاح میں دیکھنے نہایت ضروری ہوتے ہیں مدنظر
رہتے ہیں مثلاً اخلاقی اور دینی حالت ، خاندانی حالت ، مالی حالت تمدنی مناسبت، طبائع کی موافقت،
عمر ، صحت وغیرہ.ظاہر ہے کہ اگر دو نو جوانوں کو بغیر کسی قسم کے مشورہ اور ولایت کے سہارے کے یونہی
اکیلا چھوڑ دیا جاوے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے طور پر شادی کر لیں تو چونکہ نو جوانوں میں عموماً جذبات کا
زور ہوتا ہے اور مستثنیات کو الگ رکھتے ہوئے یہ جذبات بھی زیادہ تر شہوانی محبت کا رنگ رکھتے ہیں اس
لئے دوسرے امور کا نظر انداز ہو جانا بالکل اغلب ہوتا ہے اور عملاً سارا معیار صرف وقتی جذبات پر آجاتا
ہے جس کا نتیجہ اکثر خطر ناک نکلتا ہے لیکن ولایت کے انتظام میں یہ خطرہ بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ
لڑکی کے جذبات کے ساتھ ساتھ ولی کے عقل و تجربہ کی شمع بھی اپنا کام کرتی ہے.پس ولایت کا انتظام
ایک نہایت ہی مبارک انتظام ہے جس میں ایک طرف تو عورت کی جائز آزادی اور اس کا حق انتخاب قائم
رہتے ہیں اور دوسری طرف وہ شریر اور شاطر لوگوں کے دام تزویر میں پھنسنے یا محض جذباتی رو میں بہہ کہ
عقل و تجربہ کے مشورے کو خیر باد کہہ دینے کے بدنتائج سے بچ جاتی ہے.۹ - اسلامی نکاح میں مہر ایک ضروری شرط ہے یعنی مرد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق
کوئی رقم یا جائیداد یا چیز جس کا فیصلہ فریقین کی رضامندی پر موقوف ہوتا ہے عورت کو دے لیے یہ مہر خاوند
کے ذمہ ایک قانونی قرض کا رنگ رکھتا ہے اور اس کی مالک اور متصرف کلیتًا عورت ہوتی ہے.نیز یہ مہراس
حصہ کے علاوہ ہوتا ہے جو عورت کو اس کے خاوند کی وفات پر بطور ورثہ کے ملتا ہے.گویا اسلام میں عورت
کو تین مختلف ذریعوں سے مال پہنچتا ہے.اول اس کے والدین وغیرہ کی طرف سے بطور ورثہ کے یے
دوسرے اس کے خاوند کی طرف سے بطور ورثہ کے کے تیسرے مہر کے ذریعہ سے اور اس پر لطف یہ
ہے کہ عورت کے ذمہ خرچ کوئی نہیں ہوتا.-1+
خاوند اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کے ضروری اخراجات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے.اور یہ خرچ
مہر وغیرہ کے علاوہ ہوتا ہے.ا : سورة بقرة : ۲۳۸ - سورة نساء : ۲۶،۲۵ نیز مشکوۃ کتاب النکاح باب الصداق
: سورۃ نساء : ۱۳،۱۲
۳ : سورۃ نساء : ۱۳
سورة بقرة :۲۳۴ و سورة نساء: ۳۵ و سورة طلاق: ۸،۷ نیز بخاری ابواب النفقات و مسلم کتاب الحج باب
حجتہ النبی صلعم وابوداؤ د کتاب النکاح باب فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
Page 718
٧٠٣
-11
۱۱- اگر عورت و مرد نکاح کے وقت آپس میں کوئی خاص معاہدہ یا شرائط کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کی
پابندی دونوں پر واجب ہوگی.مگر وہ کوئی ایسی شرائط نہیں کر سکتے جن سے شریعت کے کسی حکم کا بطلان
لازم آئے ہے اور نہ کوئی ایسی شرط کر سکتے ہیں جو اخلاقاً قابل اعتراض ہو یا جس کے نتیجہ میں کسی تیسرے
فریق پر سختی لازم آتی ہو.اس اصل کے ماتحت اسلام میں اس بات کی اجازت سمجھی جائے گی کہ اگر کوئی
عورت اپنے لئے سوکن کے وجود کو نا قابل برداشت یقین کرتی ہے تو وہ نکاح کے وقت خاوند کے ساتھ یہ
شرط کرلے کہ اس کے ہوتے ہوئے خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا یعنی یا تو وہ دوسری شادی بالکل ہی
نہیں کرے گا یا پہلے اسے طلاق دے کر جدا کر لے گا تو پھر دوسری شادی کرے گا.اور چونکہ اسلام میں
تعدد ازدواج کا حکم نہیں ہے بلکہ صرف خاص حالات کے لئے اجازت ہے اور ایسی شرط سے کسی تیسرے شخص
پر بھی کوئی نا واجب اثر نہیں پڑتا اس لئے ایسا معاہدہ نا جائز نہ ہوگا.ہے
۱۲.اس انتظامی فرق کے سوا کہ خاوند نظام ابلی کا امیر ہوتا ہے اسلام میں عورت ومرد کے مساویانہ حقوق
تسلیم کئے گئے ہیں اور اس ابلی امارت میں بھی خاوند بالکل آزاد نہیں ہے بلکہ اسے حکم ہے کہ اپنی بیوی
کے ساتھ محبت اور خوش اخلاقی اور دلداری اور عفو کا سلوک کرے اور گوا سے گھر کا امیر ہونے کی حیثیت
میں تادیب کا بھی حق ہے مگر یہ تادیب مناسب اور واجبی ہونی چاہئے.بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا اس
قدر تا کیدی حکم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَاهْلِهِ
یعنی ”اے مسلمانو! تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنے میں سب
بخاری کتاب النکاح باب الشروط فی النكاح وباب الشروط التي لا تحل - نیز تر ندى ابــواب النكاح بــاب
ماجاء في الشرط عند عقدة النكاح بخاری کتاب البیوع باب اذا اشترط شروطافي البيع لاتحل
بخاری کتاب النکاح باب الشروط التي لا تحل
موطا كتاب النكاح مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحَ نیز چشمه معرفت مصنفہ مقدس بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ
صفحه ۲۳۷، ۲۳۸
سورة بقرة : ۲۲۴ تا ۲۲۷
: سورة نساء : ۲۱،۲۰ نیز بخاری کتاب النکاح باب حسن المعاشرت مع الاهل
ی سورۃ نساء : ۳۵ و بخاری کتاب النکاح باب ما يكره من ضرب النساء وابوداؤد کتاب النکاح باب في حق
المرأة على زوجها
ترندی وابن ماجه بحوالہ مشکوۃ کتاب النکاح باب عشرة النساء فصل ثاني
Page 719
۷۰۴
سے اچھا ہے.اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کی مثال پسلی کی ہڈی کی ہے جو خلقاً خمدار ہوتی ہے
اور جسے اگر کوئی انسان سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنا کام نہیں دے سکے گی جو اس کے خدار ہونے
کے ساتھ وابستہ ہے.اور یہ بھی نتیجہ ہوگا کہ وہ ٹوٹ جائے گی.اسی طرح عورت بھی فطر تا خمدار ہے یعنی
اس کی طبیعت میں بعض خاص ادا ئیں رکھی گئی ہیں جو ہیں تو بظاہر کجیاں مگر حقیقتاً انثیت کی جان ہیں.اگر اس
کے اس فطری خم کو کوئی شخص سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ اسے سیدھا تو نہیں کر سکے گا مگر یہ نتیجہ ضرور ہوگا کہ
پسلی کی ہڈی کی طرح عورت ٹوٹ جائے گی.یعنی یا تو وہ اپنے خاوند کے گھر میں ماہی بے آب کی طرح
تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے گی اور یا جدائی اور طلاق تک نوبت آئے گی.پس انسان کو چاہئے کہ عورت
کے اس فطری خم کو جو اس کی اُنثیت کے ساتھ لازم و ملزوم کے طور پر ہے سیدھا کرنے کی بے سود کوشش نہ
کرے بلکہ اسی خم کے ساتھ اس کے ساتھ نبھاؤ کرے.اور آپ نے فرمایا إِنَّ أَعْوَجَ شَيْ ءٍ فِي الضّلْعِ
اغلا 16 پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ ہی سب سے اونچا ہوتا ہے.“ یعنی حقیقتا عورت کا یہ فطری خم ہی
اس کی نوع کا کمال ہے اور ایک عورت اپنی انثیت میں جتنی کامل ہوگی اتنا ہی اس میں یہ فطری خم زیادہ ہوگا
کیونکہ یہ اس کی مخصوص نوعیت کی جان ہے اس نہایت درجہ حکیمانہ ارشاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے مرد کی ذہنیت کو عورت کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملہ میں ایک نہایت صحیح اور فطری بنیاد پر قائم فرما
دیا ہے اور یہ بات مسلمانوں کے ذہن نشین فرمائی ہے کہ اگر عورت کے بعض مخصوص انداز غلط استعمال یا غلط
اظہار کی وجہ سے بعض اوقات تمہارے لئے تکلیف و پریشانی کا موجب ہو جائیں تو ان کی مناسب اصلاح
تو کرو مگر ان کی وجہ سے گھبرا کر ان کو بالکل مٹا دینے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ عورت کی فطرت کا حصہ ہیں اور
اگر وہ صحیح حدود کے اندر رہیں گے تو وہی تمہاری اہلی خوشی کی بنیاد بن جائیں گے.۱۳ - عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام جائز امور میں خاوند کی اطاعت کرے.اس کے ساتھ محبت وامتنان
اور وفاداری کا نبھاؤ کرے.اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرے.اس کے بچوں کی تربیت
کرے اور اس کے خانگی امور کا انتظام کرے.چونکہ عورت کے حقوق مرد پر اور مرد کے حقوق عورت پر اسلام میں ایک قانونی رنگ رکھتے ہیں
مسلم کتاب الرضاع باب الوصية بالنساء بخاری کتاب النکاح باب الوصاءة بالنساء
سورة نساء: ۳۵ نیز بخاری کتاب النکاح باب الى من ينكح واى النساء خير وباب كُفْرَانُ الْعَشِير وباب المرأة
راعية في بيت زوجها وبابِ لَا تُطِعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ نيز ديه مشكوة كتاب النکاح باب عِشْرَةُ النِّسَاءِ
Page 720
۷۰۵
اس لئے ان کے باہمی تنازعات عدالت میں جاسکتے ہیں.چنانچہ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان عورتیں اپنے خاوندوں کی شکائتیں لایا کرتی تھیں اور آپ ان میں فیصلہ
فرماتے تھے.اور ان کے حقوق ان کو دلواتے اور ہر طرح ان کی دلداری فرماتے تھے.حتی کہ ان حقوق
اور اس قسم کے مربیانہ سلوک کی وجہ سے صحابہ میں یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ اسلام نے تو گویا عورتوں کو
آزاد کر دیا ہے..۱۵.تعدد ازدواج اور دیگر متعلقہ مسائل کے متعلق چونکہ دوسرے موقع پر مفصل بحث گزرچکی ہے اس لئے
اس جگہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے
طلاق کے قانون کا ڈھانچہ اس طرح پر سمجھنا چاہئے کہ :
۱- چونکہ نکاح ایک سول معاہدہ ہے اس لئے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے مگر اسلام نے صرف انتہائی حالات میں
اس کے توڑنے کی اجازت دی ہے جبکہ کوئی اور چارہ نہ رہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے
تھے کہ اَبغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللهِ الطَّلاق یعنی جن باتوں کو خاص مصالح کے ماتحت خدائی شریعت
میں جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے ان میں طلاق خدا کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے“.اس اصل کے
ماتحت اسلام نے ازدواجی رشتہ کو گویا ایک گونہ تقدس اور دوام کا رنگ دے دیا ہے.اور مسلمانوں کو یہ
ہدایت دی گئی ہے کہ وہ رشتہ نکاح کے منقطع کرنے میں کبھی بھی جلدی نہ کریں بلکہ انتہائی احتیاط سے کام
لیں.مگر ایک جامع اور عالمگیر شریعت کی حیثیت میں اسلام نے اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا کہ
مرد و عورت کے تعلقات میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس رشتہ کا خوشگوار
صورت میں قائم رہنا محال ہو جاتا ہے.اور نہ صرف خاوند و بیوی دونوں کی خانگی زندگی تلخ ہو جاتی ہے بلکہ
اس تلخی کا اثر لا زماان کے دوسرے کاموں پر بھی پڑتا ہے.ایسی صورت میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا
کہ ایک افسوس کرتے ہوئے دل کے ساتھ اس رشتہ کو منقطع کر دیا جاوے.چنانچہ اس قسم کے انتہائی حالات
کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ نے اسلام میں طلاق کا قانون جاری فرمایا ہے..اس قانون طلاق کو ( خلاف شریعت اور نا جائز نکاح کی صورتوں کو الگ رکھتے ہیں جنہیں اصطلاحاً
سورة بقرة : ۲۳۰ تا ۲۳۲
: دیکھو مشکوۃ کتاب النکاح
مسلم کتاب الرضاع باب في الايلاء عن عباس وابوداؤ د كتاب النکاح باب فِي ضَرْبِ النِّسَاءِ
: دیکھئے کتاب ہذا حالات ۲ھ
ابوداؤ دا بواب الطلاق باب فِي كَرَاهِيَةِ الطَّلَاقِ
Page 721
2+Y
نکاح باطل یا نکاح فاسد کہتے ہیں ) موٹے طور پر تین حصوں میں تقسیم شدہ سمجھنا چاہئے.اوّل فسخ نکاح کی
صورت جس کے اندر میں فقہ کی اصطلاح سے کسی قدر ہٹ کر لعان وغیرہ کی صورت کو بھی شامل کرتا
ہوں یعنی تمام وہ صورتیں جبکہ عقد نکاح کا قائم رہنا نا جائز ہو جاوے.دوم طلاق یعنی وہ صورت جبکہ
علیحدگی کی خواہش اور جدائی کی تحریک خاوند کی طرف سے ہو.سوم خلع یعنی وہ صورت جبکہ علیحدگی کی
خواہش اور جدائی کی تحریک بیوی کی طرف سے ہو.ان تینوں صورتوں کے لئے اسلام نے الگ الگ
ضابطہ مقرر فرمایا ہے.فسخ نکاح کی صورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ نکاح کا قائم رہنا نا جائز ہو جاوے.مثلاً لڑکی اپنا
حق خیارالبلوغ استعمال کرے ہے جس کی کسی قدر تشریح اوپر گزر چکی ہے.یا مثلا خاوند کو اپنی بیوی کی
عصمت کے خلاف یقین ہو جاوے مگر وہ اسے شرعی طور پر ثابت نہ کر سکے جس صورت میں اسلام یہ حکم دیتا
ہے کہ مرد وعورت ایک دوسرے کے خلاف مؤکد بعذاب حلف اٹھائیں اور پھر ان میں علیحدگی کرادی
جاوے.اس صورت کو اسلامی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں.کے
- طلاق کی صورت میں اسلامی حکم یہ ہے کہ جب مرد و عورت میں ایسے حالات پیدا ہو جاویں کہ خاوند
اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کی طرف مائل ہو جاوے تو پیشتر اس کے کہ وہ طلاق دے فریقین کے متعلقین
کو ایک موقع مصالحت کی کوشش کا ملنا چاہئے.اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاوے تو فبہا لیکن اگر وہ
کامیاب نہ ہو تو اس صورت میں خاوند کو اپنے اختیار سے بغیر عدالت میں جانے کے طلاق دینے کا حق
یہ طلاق ایسے طہر میں ہونی چاہئے جس میں خاوند بیوی اکٹھے نہ ہوئے ہوں تاکہ یہ کام
جلد بازی کے طریق پر نہ ہو کہ جب جی میں آیا طلاق دے دی اور تا عورت کی مخصوص کشش خاوند کو
اس کے اس ارادے سے روکنے کے لئے آزا در ہے.د مگر.گوخاوند بیوی کی جدائی ایک طلاق سے بھی ہو سکتی ہے مگر دو طلاقوں تک خاوند کو رجوع کا حق رہتا
و
دیکھئے مشکوۃ کتاب النکاح و کتاب الطلاق وغیرہ.نیز دیکھئے زادالمعاد فصول متعلقہ
: بداية المجتهد وزادالمعاد فصول متعلقہ
سورة نور: ۳ تا ۹ نیز بخاری کتاب الطلاق ابواب اللعان : سورة نساء : ٣٦
۵: سورة بقرة : ۲۳۰ تا ۲۳۲ وسورة نساء : ۲۶ وسورة طلاق : ۱تا ۵
بخاری کتاب الطلاق باب اول.نیز بخاری کتاب التفسیر سورۃ طلاق
Page 722
4.2
ہے اور کامل جدائی کے واسطے یہ ضروری ہے کہ طلاق تین دفعہ تین مختلف وقتوں میں دی جاوے تا کہ
مکمل علیحدگی کے لئے کسی عارضی ناراضگی میں قدم نہ اٹھایا جاسکے اور خاوند کو اپنے ٹھنڈے لمحات میں
اونچ نیچ کے سوچنے کا موقع مل جاوے.اگر کوئی شخص جوش میں آکر ایک ہی وقت میں تین طلاقیں
دے دیتا ہے تو وہ نا جائز ہوگا اور صرف ایک طلاق شمار ہوگی لے
-Y
طلاق کی صورت میں خاوند کا فرض ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کا مہر پہلے نہیں ادا کر چکا تو طلاق کے وقت اسے
ادا کرے اور اگر کوئی اور مال اس نے اپنی بیوی کو دے رکھا ہے تو وہ بھی واپس نہ لے بلکہ ممکن ہو تو اپنے
پاس سے کچھ اور بھی دے دے اور بڑی خوش معاملگی اور احسان کے طریق پر اس کام کو سر انجام دے.ے.طلاق کے بعد بھی جب تک عورت دوسری شادی کے لئے آزاد نہ ہو جاوے خاوند اس بات کا ذمہ دار
ہے کہ اپنی مطلقہ بیوی کے ضروری اخراجات کا بوجھ اٹھائے.اور اگر کوئی خوردسالہ اولاد ہے جو ماں سے
جدا نہیں ہو سکتی تو وہ بھی ماں کے پاس رہے گی اور اس کے ضروری اخراجات کا ذمہ دار باپ ہوگا..- خلع کے متعلق اسلامی قانون یہ ہے کہ چونکہ خانگی نظام کی امارت خاوند کے ہاتھ میں ہے یعنی
از روئے شریعت اور از روئے عقل وہ نہ صرف بیوی کے اخراجات کا ذمہ دار ہے بلکہ فیملی کا ہیڈ بھی وہی ہے
اور پھر دوسری طرف عورت ہوتی بھی نسبتا سادہ مزاج ہے اور چالاک لوگوں کے دھوکے میں زیادہ آسانی
کے ساتھ آسکتی ہے اس لئے بیوی کو خود بخود علیحدہ ہو جانے کا حق نہیں ہے بلکہ اس صورت میں اسلامی تعلیم
یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے عورت اپنے خاوند کے ساتھ نبھاؤ کو ناممکن خیال کرے اور دوسری طرف خاوند
اسے الگ کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو وہ حاکم کے ذریعہ علیحدگی حاصل کر سکتی ہے.اور حاکم کا یہ کام مقر رکیا
ل سورة بقرة: ۲۳۰ تا ۲۳۲ نیز ابوداؤ د کتاب النکاح باب في البتة و بخاری کتاب الطلاق باب وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
برَدِهِنَّ ونسائى عن محمود بن لبيد - بحوالہ مشکوۃ باب الخلع والطلاق فصل ثاني
: سورة بقرة : ۲۳۰ تا ۲۳۶ وسورة طلاق : ۱تا ۸
سے : سورة بقرة : ۲۳۴ وسورة طلاق : ۱ تا ۸ نیز دیکھو بخاری کتاب الطلاق باب قصة فاطمة وبداية
المجتهد وزادالمعاد فصول متعلقہ
سورة بقرة : ۲۳۴ نیز موطا وابوداؤ دباب من احق بالولدوبداية المجتهد وزاد المعاد فصول متعلقہ
۵: سورة بقرة : ۲۳۰ ۲۳۱ نیز بخاری کتاب النکاح باب الخلع و مشکوة باب الخلع وباب الولى في النكاح
نیز دیکھوهداية المجتهدوزادالمعاد فصول متعلقہ
Page 723
2.1
+1-
گیا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے حقیقی خواہش علیحدگی کی موجود ہو اور وہ کسی دھو کے اور شرارت کا
شکار نہ ہو رہی ہو تو علیحدگی کا حکم دے دے اور اس سوال میں زیادہ نہ پڑے کہ عورت کی علیحدگی کی خواہش
مناسب یا پسندیدہ ہے یا نہیں.اس اصل کے ماتحت اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی دوسری شادی کو
اپنے لئے واقعی نا قابل برداشت پاتی ہے تو وہ محض اسی بنا پر ضلع کا مطالبہ کر سکتی ہے.۹- اگر خاوند اپنی بیوی کو کوئی مال یا جائیداد علاوہ از اخراجات زندگی دے چکا ہو اور وہ اس کی واپسی
کا مطالبہ کرے تو خلع کی صورت میں عدالت اس کی واپسی کا بوجھ مناسب حد تک عورت پر ڈال سکتی ہے.فسخ نکاح اور طلاق اور خلع کی ان صورتوں میں جن میں خاوند اور بیوی کے اکٹھے ہونے کے بعد
علیحدگی ہوئی ہو عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کی علیحدگی پر ایک مقررہ میعاد
جسے موٹے طور پر تین ماہ کہہ سکتے ہیں نہ گزر جاوے یا حمل کی صورت میں وضع حمل نہ ہو جاوے.اس معیاد
کو شریعت کی اصطلاح میں عدت کہتے ہیں."
یہ اس قانون شادی و طلاق کا ڈھانچہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی حکم کے ماتحت
مسلمانوں کے واسطے مقرر فرمایا.اس نظام میں اسلامی قانون شادی کی خوبی تو ہمیشہ ہی اہل عقل وخرد کے
نزدیک مسلم رہی ہے.مگر یہ ایک شکر کا مقام ہے کہ صدیوں کی ٹھوکروں کے بعد اب دنیا میں آہستہ آہستہ
اسلامی قانون طلاق کی طرف بھی آرہی ہے.چنانچہ مختلف مسیحی ممالک میں کم و بیش اسی لائن پر طلاق
کا قانون بنتا چلا جارہا ہے جو اسلام نے پیش کی ہے.گو مغربی ممالک کی روش میں یہ اندیشہ بھی ضرور پایا
جاتا ہے کہ کہیں طلاق زیادہ عام نہ ہو جاوے یعنی اس معاملہ میں لوگوں کے لئے حد اعتدال سے زیادہ
آزادی کا دروازہ نہ کھول دیا جاوے کیونکہ جہاں ایک طرف طلاق کے دروازے کو بالکل بند کر دینا یا ایسی
نا واجب شرائط کے ساتھ مشروط کر دینا جو عملاً بند کر دینے کے مساوی ہوسخت نقصان دہ ہے وہاں اسے
نا واجب طور پر زیادہ کھول دینا بھی کم ضرر رساں نہیں اور یقیناً اصلاح کا رستہ وہی ہے جو اسلام نے اعتدال
پر قائم رہتے ہوئے پیش کیا ہے.بخاری کتاب الطلاق باب الخلع وابوداؤ دابواب الطلاق باب الخلع
چشمه معرفت صفحه ۲۳۸ کشتی نوح صفحه ۷۲
: سورة بقرة : ۲۳۰ ۲۳۱ نیز بخاری کتاب النکاح باب الخلع نیز دیکھومشکوۃ باب الخلع
: سورة بقرة : ۲۲۹ وسورة طلاق : ۵
Page 724
2.9
"
اس جگہ یہ ذکر بھی بے موقع نہ ہوگا کہ میور صاحب نے اسلامی قانون طلاق پر یہ دلآزار طعن کیا ہے
کہ اس کی رو سے دو طلاقوں تک تو خاوند کو اپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے لیکن تیسری طلاق
ہو چکنے کے بعد اسے یہ حق صرف اس صورت میں ہے کہ عورت کسی اور شخص کے نکاح میں آ کر پھر اس سے
علیحدگی حاصل کرے اور اس کے بعد میور صاحب نہایت جرات کے انداز میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں
میں اس بات کو جائز رکھا گیا ہے کہ ایک کرایہ دار مرد کی خدمات حاصل کر کے اس کے ساتھ ایسی عورت
کو اس شرط کے ساتھ بیاہ دیا جاوے کہ وہ اسے نکاح کے بعد طلاق دے دے گا تا کہ وہ عورت اپنے اصل
خاوند کی طرف لوٹ سکے.یہ اعتراض میور صاحب کے پرلے درجہ کے تعصب اور اگر تعصب نہیں تو پر لے
درجہ کی لاعلمی پر مبنی ہے.اسلام ہرگز یہ تعلیم نہیں دیتا کہ سابق خاوند کے واسطے عورت کو جائز کرنے کے لئے
یہ حیلہ کیا جاوے کہ عورت کو کسی اور آدمی سے بیاہ کر پھر اس سے علیحدگی حاصل کی جاوے بلکہ حق یہ ہے کہ
اسلام اس قسم کے حیلہ کو ایک سخت نا پاک اور لعنتی فعل قرار دیتا ہے.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کرتے تھے کہ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَم دو یعنی وہ شخص خدا کی لعنت کے نیچے ہے جو کسی
عورت کے ساتھ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ تا بعد میں اسے طلاق دے کر اس کے سابقہ خاوند کے لئے
اسے جائز کر دے اور اسی طرح وہ شخص بھی خدا کی لعنت کے نیچے ہے جو کسی دوسرے شخص سے اپنی سابقہ
بیوی کا اس غرض سے نکاح کرواتا ہے کہ تا وہ شخص اس سے طلاق حاصل کرے پھر اس کے نکاح میں
آسکے.‘اور حضرت
عمر خلیفہ ثانی تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کا فعل کرے گا تو
میں اسے زنا کی سزا دوں گا.اندریں حالات اس سے بڑھ کر دیدہ دلیری کیا ہوگی کہ اسلام کی طرف
اس نا پاک طریق کو منسوب کیا جاوے.اسلامی تعلیم کا منشا جسے میور صاحب نے نہیں سمجھایا نہیں سمجھنا چاہا صرف یہ ہے کہ جب تین طلاقیں
ہو چکیں تو اس کے بعد مرد و عورت اکٹھے نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ عورت اپنی جائز ضرورت و غرض کے
ماتحت کسی اور آدمی کے نکاح میں آئے اور اس کے بعد وہ اپنے لئے نئے خاوند کی وفات یا کسی حقیقی
اختلاف کی بنا پر طلاق کی وجہ سے نہ اس غرض سے کہ وہ اپنے پہلے خاوند کی طرف لوٹ سکے پھر شادی
ل لائف آف محمد مصنفه سرولیم میور صفحه ۳۲۶،۳۲۵
ابوداود كتاب النکاح باب فى التحليل وترمذی ابواب النکاح
سے تفسیر ابن کثیر بحث آیت حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
Page 725
21•
کے لئے آزادہ ہو جاوے تو اس صورت میں باہم رضامندی کے ساتھ پہلا خاوند اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ
پھر نکاح کرسکتا ہے.اور اس قانون میں حکمت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یکے بعد دیگرے
تین دفعہ طلاق دے چکتا ہے تو اس لیے تجربہ کے بعد یہی سمجھا جائے گا کہ اب ان کی اہلی زندگی کسی
صورت میں خوشگوار نہیں رہ سکتی.اس لئے اب انہیں پھر اکٹھے ہو کر ایک مزید تلخ تجربہ نہیں کرنا چاہئے
بلکہ کامل طور پر علیحدہ ہو جانا چاہئے اور ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونے کا خیال دل سے نکال دینا
چاہئے لیکن اگر اس کے بعد عورت کسی اور مرد کے نکاح میں آئے اور اس کے ساتھ متا ہلا نہ زندگی گزارے
اور پھر کسی حقیقی اور جائز وجہ سے اس نئے خاوند سے اس کی علیحدگی ہو جائے یا اس کا نیا خاوند فوت
ہو جائے اور اس کے بعد وہ اور اس کا سابقہ خاوند باہم رضامندی کے ساتھ پھر ا کٹھے ہونا چاہیں تو ان کے
رستے میں کوئی روک نہیں ہونی چاہئے.کیونکہ علاوہ اس کے کہ ان کی شادی میں کوئی امر اصولا مانع
نہیں ہے ایسی صورت میں یہ امید کرنا ہر گز بعید از قیاس نہیں کہ اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ کر سکیں
گے کیونکہ ایک عرصہ تک ایک دوسرے سے الگ رہنے اور اس عرصہ میں ایک تیسرے شخص کے ساتھ معاملہ
پڑنے کے نتیجہ میں ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر پیدا ہو جانا بالکل ممکن اور قرین قیاس ہے اور یہ
مسئلہ بھی دراصل اسلام نے اس غرض سے خاص طور پر بیان کیا ہے کہ اگر ایک طرف اہلی زندگی کے تلخ
تجربات کے سلسلہ کو محدود کیا جاوے تو دوسری طرف لوگوں میں اس خیال کا بھی سد باب کیا جاوے کہ گویا
تین طلاقوں کا وجود اپنی ذات میں کوئی حرمت کی وجہ ہے اور یہ کہ تین طلاقوں کے بعد خاوند بیوی کے
اکٹھے ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے.علاوہ ازیں تین طلاقوں کے بعد بھی تجدید نکاح کا دروازہ کھلا رکھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تا
اس سے لوگوں میں نکاح کے تقدس اور دوام کا احساس پیدا کیا جاوے اور یہ خیال قائم کیا جاوے کہ جب
دومرد وعورت کا ایک دفعہ آپس میں ازدواجی تعلق قائم ہو جاوے تو پھر انتہائی کوشش اس تعلق کے نبھانے کی
ہونی چاہئے اور اگر کسی وجہ سے درمیان میں یہ تعلق ٹوٹ بھی جاوے اور اس کا پھر قائم ہونا محال بھی
ہو جاوے تو پھر بھی آئندہ چل کر کوئی ایسا موقع جبکہ جائز طور پر اس تعلق کے دوبارہ جوڑے جانے کی امید
ہو سکے ضائع نہیں جانے دینا چاہئے.پس میور صاحب نے جس مسئلہ کو ایک غلط اور نا پاک صورت دے کر
اس پر اعتراض کیا ہے وہ دراصل اپنی حقیقی صورت میں اسلامی تعلیم کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جسے افسوس
ہے کہ سرولیم کی آنکھ دیکھ نہیں سکی.-
Page 726
مدنی زندگی کے پہلے دور کا خاتمہ
اور اسلامی طریق حکومت
ایک نئے دور کا آغاز غزوہ بنو قریظہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے پہلے
دور اور ہماری کتاب کی دوسری جلد کا خاتمہ ہوتا ہے.یہ دور کن حالات
میں گزرا؟ اسلام کی حفاظت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا؟
مسلمانوں پر کیسی کیسی نازک گھڑیاں آئیں؟ اندرونی اور بیرونی خطرات نے کیا کیا مہیب صورتیں اختیار
کیں ؟ ان سولات کا کسی قدر مفصل جواب اوپر گذر چکا ہے.یہ کہنا بالکل بے جا نہ ہو گا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا پہلا دور ایک مسلسل زلزلہ کا رنگ رکھتا تھا جو پانچ سال کے طویل عرصہ میں
جسے مصائب نے احساسی طور پر اور بھی لمبا کر دیا تھا مدینہ کی سرزمین کو خطر ناک طور پر جنبش دیتارہا اور اس
زلزلہ کے بعض دھکے اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسے تباہ کن تھے کہ اگر خدا کی نصرت شامل حال نہ ہوتی تو یقیناً
یہ دھکے مدینہ کی سرزمین کو بالکل تہ و بالا کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے خاک میں سلا دیتے اور جیسا کہ
ہم دیکھ چکے ہیں اس زلزلہ کے آتش فشاں منبع کی ایک شاخ یہود کے قلعوں میں ہو کر عین مدینہ کی دیواروں
کے نیچے پہنچی ہوئی تھی.اس زلزلہ کا سب سے بڑا دھکا غزوہ احزاب میں پیش آیا جبکہ خونخوار اتحادیوں
کے جنگی نعروں اور ان کے عربی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے مدینہ کی زمین گویا لفظا لرزہ کھا گئی تھی اور
مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آنے لگے تھے اور اس زلزلہ کو بدعہد یہود کی غداری نے اور بھی زیادہ خطرناک
صورت دے دی تھی لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے یہ حملہ کفارمکہ کی عداوت کا آخری نقطہ ثابت
ہوا جس کے بعد گوان کی دلی عداوت اور فتنہ انگیزی تو اسی طرح قائم رہی مگر انہیں مدینہ پر حملہ آور
ہونے کی توفیق نہیں ملی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی کہ الآنَ نَغْزُوُهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا
Page 727
۷۱۲
( یعنی ان لوگوں
کی فتنہ انگیزی اور دشمنی کی وجہ سے آئندہ ہمیں تو ان کے خلاف فوج کشی کے موقعے ملتے
رہیں گے مگر انہیں ہمارے خلاف مدینہ پر چڑھائی کرنے کی توفیق نہیں ملے گی ) حرف بحرف پوری ہوئی
اور اس طرح مدنی زندگی کے پہلے اور دوسرے دور میں ایک مابہ الامتیاز قائم ہو گیا.علاوہ ازیں چونکہ
بنو قریظہ کے خاتمہ کے ساتھ مدینہ میں یہودی آبادی کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد مدینہ کے شہر
میں سوائے مسلمانوں یا مسلمان کہلانے والے منافقوں یا مسلمانوں کے توابع کے اور کوئی قوم باقی نہیں
رہی تھی جو مسلمانوں کے مقابلہ پر کھڑی ہو سکتی یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بر ملا سرتابی کرنے
کی جرات کرتی.اس لیے اس وقت سے مدینہ میں ایک خالص اسلامی حکومت کی بنیاد بھی قائم ہوگئی.گویا
اس نئے دور کی جو غزوہ بنو قریظہ کے بعد سے شروع ہوا، دو نمایاں خصوصیات تھیں.اوّل کفار کے ان
حملوں کا جو مدینہ کے خلاف ہوتے تھے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور اس کے نتیجہ میں میدان کارزار
مدینہ کے قرب و جوار سے ہٹ کر دور دراز کے علاقوں کی طرف منتقل ہو گیا.دوم مدینہ کا شہر
سیاست وحکومت کے لحاظ سے ایک خالص اسلامی سلطنت کی صورت اختیار کر گیا جس میں کسی غیر حکومت
یا غیر قوم یا غیر مذہب کا دخل نہیں تھا.اور پھر یہی مرکزی حکومت آہستہ آہستہ وسعت اختیار کر کے
بالآخر دنیا کے ایک بڑے حصہ پر چھا گئی.یہ محیر العقول تغیر پانچ سال کے قلیل عرصہ میں کس طرح ممکن ہو گیا ؟ اس سوال کا حقیقی جواب اس دنیا
کے مادی علوم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اور اسے پوری طرح وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو روحانی تصرفات کا علم
رکھتا ہو اور اس خدائی سنت سے واقف ہو جو قدیم سے نبیوں کے ساتھ رہی ہے مگر یہ امور تاریخ کا حصہ نہیں
ہیں.ظاہری اسباب کے لحاظ سے جو باتیں مسلمانوں کی اس بے نظیر کامیابی کا باعث سمجھی جاسکتی ہیں ان
میں مندرجہ ذیل باتیں خاص طور پر نمایاں اثر رکھتی تھیں.مسلمانوں کا اتحاد، ان
کی تنظیم ، ان کا اپنے مقصد
کے لیے بے نظیر استقلال.ان کی قربانی کی روح.اُن کا یہ کامل یقین کہ ہم حق وصداقت کی خاطر لڑ رہے
ہیں.ان کا یہ گہرا احساس کہ ہم اس قدر بے سروسامان ہیں کہ جب تک ہم اپنی انتہائی طاقت کو بے دریغ
صرف کر دینے کے لیے تیار نہیں ہونگے ہماری حفاظت کی کوئی صورت نہیں ہے.اور پھر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی بے نظیر مقناطیسی شخصیت اور اعلیٰ درجہ کی جنگی تدابیر وغیر ذالک.ان تاثیرات نے مسلمانوں کی
مٹھی بھر جماعت میں وہ طاقت بھر دی تھی جسے عرب کی لا تعدا د افواج کا نہایت وحشیانہ مظاہرہ بھی مغلوب
نہیں کر سکا اور اس پانچ سالہ جنگ کے نتیجہ میں کفار عرب نے اس بات کو یقینی طور پر سمجھ لیا کہ اب مدینہ پر
Page 728
۷۱۳
حملہ آور ہو کر اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کا خیال ایک خیال باطل ہے جو کبھی بھی پورا
نہیں ہوسکتا.اور یہ کہ اب انہیں مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے اور تدابیر سے کام لینا چاہئے.کفار کی
یہ ذہنی تبدیلی اسلام کے لیے ایک نئے دور کے آغاز کا نشان تھی.اسلامی طریق حکومت چونکہ اس نئے دور کی دو نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مدینہ میں
خالص اسلامی حکومت کا قیام تھی اس لیے اس موقع پر اس اصولی تعلیم کا ذکر
کرنا نا مناسب نہ ہوگا جو بانی اسلام نے حکومت کے طریق کے متعلق پیش فرمائی ہے.اس کے متعلق
سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہئیے کہ جیسا کہ دوسرے دنیاوی امور میں اسلام کا طریق ہے اس معاملہ میں
اسلام نے صرف ایک اصولی تعلیم دی ہے اور تفصیلات کے تصفیہ کو ہر زمانہ اور ہر ملک اور ہر قوم کے
حالات پر چھوڑ دیا ہے.اور دراصل اس قسم کے معاملات میں یہی طریق عقل مندی اور میانہ روی کا
طریق ہے کہ صرف اصولی ہدایت پر اکتفا کیا جاوے اور تفصیلات میں دخل نہ دیا جاوے.کیونکہ اگر ایسا
نہ ہو اور حالات کے اختلاف کا لحاظ رکھنے کے بغیر ہر زمانہ میں ہر قوم پر ایک ہی ٹھوس غیر مبدل اور تفصیلی
قانون جاری کر دیا جاوے تو ظاہر ہے کہ قانون شریعت رحمت کی بجائے ایک زحمت ہو جاوے اور
ہدایت کی بجائے ضلالت کا سامان پیدا کر دے.پس اسلام نے کمال دانشمندی کے ساتھ اس معاملہ میں
صرف ایک اصولی ہدایت دی ہے.جو تفصیلات کے مناسب اختلاف کے ساتھ سب قسم کے حالات پر
یکساں چسپاں ہوتی ہے.حکومت کا اصل حق صرف جمہور کو حاصل یہ اصولی ہدایت یہ ہے کہ انبیاء ومرسلین کے
معاملہ کو الگ رکھتے ہوئے جنہیں خدا کی طرف
ہے اور جمہور کی طرف سے افراد کو پہنچتا ہے سے اس کے ازلی حق میں سے حکومت کا حق پہنچتا
ہے سب لوگ حکومت کے حق میں برابر ہیں.یعنی اصل حکومت جمہور کی ہے اور اس حق میں کسی شخص کو
دوسروں کی نسبت فائق حق حاصل نہیں ہے.لیکن چونکہ نظام حکومت کے چلانے کے لیے ایک محدود
انتظامی حکومت کا ہونا ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت کی انتہائی باگ ڈور ایک حاکم اعلیٰ یعنی
صدر حکومت کے ہاتھ میں ہو.اس لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ باہم مشورہ کے ساتھ
جس شخص کو حکومت کے لیے سب سے زیادہ اہل سمجھیں اسے اپنا امیر مقرر کر لیا کریں.چنانچہ قرآن شریف
میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
Page 729
۷۱۴
اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ' یعنی ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ حکومت کی امانت تم اس کے اہل
لوگوں کے سپر د کیا کرو اور پھر جو لوگ اس طرح حاکم منتخب ہوں انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ لوگوں میں
عدل وانصاف کے ساتھ حکومت کریں.اس اصولی آیت میں حکومت کے حق کو امانت کے لفظ سے تعبیر کیا
گیا ہے جس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ دراصل حکومت کا حق سب لوگوں کا
مشترکہ حق ہے اور خاص افراد کو جمہور کی طرف سے ایک امانت کے طور پر ملتا ہے.پس جس شخص کو حکومت
ملے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک امانت ہے جو لوگوں کی طرف سے اسے ملی ہے.چنانچہ حدیث میں آتا ہے
کہ ایک دفعہ ابوذر صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کسی علاقے کا امیر مقرر
فرما دیں.اس پر آپ نے فرمایا:
يَا اَبَاذَرٍ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا
بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيْهَا.یعنی اے ابوذرا تم ایک ضعیف انسان ہو اور حکومت ایک امانت
ہے اور قیامت کے دن وہ ذلت و ندامت کا موجب ہو گی سوائے اس شخص کے جو اس کے پورے پورے
حقوق ادا کرے.‘ اس حدیث میں حکومت کو امانت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی یہ حکومت کا حق صرف
جمہور کو حاصل ہے اور کسی خاص فرد کو اس کا حق جمہور کی طرف سے صرف ایک امانت کے طور پر ملتا ہے.چونکہ حکومت ایک امانت ہے اس لیے حاکم اعلیٰ کا تقرر تو الگ رہاما تحت حکام کے تقرر میں بھی اسلام
یہ ہدایت دیتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو حاکم مقرر نہ کیا جاوے جو خو د حکومت کا خواہشمند ہو.چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
إِنَّاوَ اللَّهِ لَا نُوَلَّى هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ E یعنی ”خدا کی قسم ہم کبھی
ایسے شخص کو حکومت کا کوئی عہدہ نہیں دیں گے جو خود اس عہدہ کو طلب کرے یا اس کا خواہشمند ہو.“
جو لوگ لوگوں کے مشورہ سے حاکم منتخب ہوں ان کی
ہدایت کے لیے اسلام میہ اصولی تعلیم ارشادفرماتا ہے:
حکومت کے لیے مشورہ ضروری ہے
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ
ا: سورۃ نساء : ۵۹
سے مسلم کتاب الامارة بابِ النَّهُى عَنْ طَلَبِ الْآمَارَةِ
صحیح مسلم کتاب الامارۃ باب كراهية الامارة
Page 730
۷۱۵
وَمِمَّا رَزَقْنُهُمْ يُنْفِقُونَ LO یعنی ” مومنوں کا یہ کام ہے کہ وہ خدا کی پوری پوری فرمانبرداری اختیار
کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں اور حکومت کے امور باہم مشورہ کے ساتھ طے کریں اور جو اموال
خدا نے انہیں دئے ہیں انہیں لوگوں پر خرچ کریں اس آیت میں حاکم کا یہ فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ امیر
منتخب ہونے کے بعد خود مختارانہ اور جابرانہ طریق اختیار نہ کرے بلکہ اس اصول کو یا در کھتے ہوئے کہ اس کی
حکومت اس کے پاس محض ایک امانت ہے رائے عامہ کو معلوم کرتا رہے اور لوگوں کے مشورہ کے ساتھ
حکومت کے فرائض سر انجام دے.چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ " یعنی اے نبی تم حکومت کے معاملات میں
لوگوں سے مشورہ لیا کرو.مگر مشورہ کے بعد جب تم کوئی رائے قائم کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو.“ یہ ہدایت
قرآنی محاورہ کے مطابق صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے خلفاء اور متبعین کے لیے بھی ہے.خلاصہ کلام یہ کہ طریق حکومت کے معاملہ میں اسلام صرف دو اصولی ہدا یتیں دیتا ہے.اوّل یہ کہ
حکومت کا حق سب لوگوں کا مشترک حق ہے اور ایسی صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے میں سے بہترین
شخص کو باہم مشورے کے ساتھ امیر منتخب کیا کریں.دوسرے یہ کہ جو شخص امیر بنے اور حکومت کی باگ ڈور
اس کے ہاتھ میں آئے اس کا فرض ہے کہ اس امانت کو حق و انصاف کے ساتھ ادا کرے اور سیاست و حکومت
کے جملہ اہم امور لوگوں کے مشورہ کے ساتھ سرانجام دے.گویا حکومت کے معاملہ میں اسلام نے ورثہ
کے حق کو قطعاً تسلیم نہیں کیا اور نہ اس بات کو جائز رکھا ہے کہ کوئی حاکم رائے عامہ کو نظر انداز کرتے ہوئے
اور مشورہ کے طریق کو چھوڑ کر حکومت میں استبدادی اور خود مختارانہ طریق اختیار کرے لیکن جیسا کہ موجودہ
زمانہ میں بھی یہ اصول ویٹو وغیرہ کی صورت میں عام طور پر مسلم ہے اسلام نے استثنائی حالات میں امیر
کے لیے یہ حق تسلیم کیا ہے کہ وہ اگر ضروری سمجھے تو کثرت رائے کے مشورہ کو رد کر دے تے مگر اسلامی
شریعت کی رو سے امیر بہر حال اس بات کا پابند قرار دیا گیا ہے کہ کوئی اہم معاملہ مشورہ لینے کے بغیر طے نہ
کرے حتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمر نے جو اسلامی سیاسیات میں نہایت
ماہر سمجھے گئے ہیں یہاں تک فرمایا ہے کہ لَا خِلَافَةَ إِلَّا بِالْمَشْوَرَةِ یعنی کوئی اسلامی حکومت مشورہ کے
انتظام کے بغیر جائز تسلیم نہیں کی جاسکتی.“
: سورة آل عمران : ۱۶۰
: سورۃ شوری : ۳۹
: سورة آل عمران : ۱۶۰
: إِزَالَةُ الْخِفَاءِ عَنْ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ
Page 731
217
یہ وہ اصولی ہدا یتیں ہیں جو اسلام نے حکومت کے طریق کے متعلق جاری فرمائی ہیں.لیکن جیسا کہ
اوپر بیان کیا جا چکا ہے اسلام نے ان اصولی ہدایات کے سوا اس مسئلہ کی تفصیلات میں کوئی دخل نہیں
دیا.مثلاً اس قسم کے سوالات کے متعلق اسلام نے کوئی معین ہدایات نہیں دیں کہ امیر یعنی صد ر حکومت کے
انتخاب کے متعلق کس طریق پر مشورہ ہونا چاہیے اور مجلس شوری کی تقویم کون سے اصول پر مبنی ہو اور جب
کوئی امیر منتخب ہو جاوے تو وہ امور مملکت میں پبلک سے مشورہ لینے کے متعلق کیا طریق اختیار کرے اور
مشورہ میں کس قسم کے امور پیش ہوں اور نظام حکومت کی جزئیات کیا ہوں وغیر ذالک.یہ باتیں اور اسی قسم
کی دوسری تفصیلات ہر ملک اور ہر قوم اور ہر زمانہ کے حالات پر چھوڑ دی گئی ہیں.حضرت عمرؓ اور حضرت عثمان کی اس جگہ بعض لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوسکتا ہے کہ اگر
اسلامی تعلیم کی رو سے امیر یا خلیفہ کا تقرر مشورہ اور انتخاب کے
خلافت کس طرح قائم ہوئی؟ طریق پر ہونا ضروری ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر خلیفہ ثانی
کا تقر ر اس طریق پر نہیں ہوا بلکہ انہیں حضرت ابوبکر خلیفہ اول نے خود مقرر کر دیا تھا اور پھر کیا وجہ ہے کہ
حضرت عثمان خلیفہ ثالث کا تقرر بھی رائے عامہ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ حضرت عمر نے اس حق کو چھ سات
صحابہ تک محدود کر دیا تھا اور بالآخر کیا وجہ ہے کہ امراء بنی امیہ اور بنی عباس وغیرہ ہمیشہ اپنا ولی عہد خود مقرر
کر دیتے تھے جو عموماً کوئی بیٹا یا قریبی رشتہ دار ہوتا تھا بلکہ بعض اوقات یہ فیصلہ کر جاتے تھے کہ ہمارے بعد
فلاں شخص امیر ہو اور اس کے بعد فلاں اور اس کے بعد فلاں اور ان کے زمانہ میں کبھی بھی مشورہ اور انتخاب
کے طریق پر امیر کا تقررنہیں ہوا ؟
اس شبہ کے جواب میں پہلے ہم حضرت عمر کی خلافت کے سوال کو لیتے ہیں.سو جاننا چاہئے کہ بیشک
اسلام میں خلافت وامارت کے قیام کے لئے مشورہ اور انتخاب کا طریق ضروری ہے مگر جیسا کہ ہم اوپر
بیان کر چکے ہیں مشورہ اور انتخاب کے طریق کی نوعیت اور اس کی تفاصیل کے متعلق اسلام نے کوئی خاص
شرط یا حد بندی مقرر نہیں کی بلکہ اس قسم کے فروعی سوالات کو وقتی حالات پر چھوڑ دیا ہے اور ظاہر ہے کہ
مختلف قسم کے حالات میں مشورہ اور انتخاب کی صورت مختلف ہو سکتی ہے اور اس اصل کے ماتحت اگر نظر غور
سے دیکھا جاوے تو حضرت عمرؓ کی خلافت کا قیام بھی درحقیقت مشورہ اور انتخاب کے اصول کے ماتحت ہی
ثابت ہوتا ہے.حضرت عمرؓ کی خلافت کا معاملہ یوں طے ہوا تھا کہ جب حضرت ابوبکر جو ایک منتخب شدہ
خلیفہ تھے فوت ہونے لگے تو چونکہ اس وقت تک ابھی فتنہ ارتداد کے اثرات پوری طرح نہیں مٹے تھے اور
Page 732
Z12
خلافت کا نظام بھی ابھی ابتدائی حالت میں تھا حضرت ابو بکڑ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ آئندہ خلافت کے لیے
سب سے زیادہ موزوں اور اہل شخص حضرت عمر ہیں اور یہ کہ اگر خلیفہ کے انتخاب کو رائے عامہ پر چھوڑ دیا
گیا تو ممکن ہے کہ حضرت عمر اپنی طبیعت کی ظاہری تختی کی وجہ سے انتخاب میں نہ آسکیں اور امت محمدیہ میں
کسی فتنہ کا دروازہ کھل جاوے، اہل الرائے صحابہ کو بلا کر ان سے مشورہ لیا اور اس مشورہ کے بعد حضرت عمرؓ
کو جن کا حضرت ابوبکر کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا بلکہ قبیلہ تک جدا تھا اپنا جانشین مقرر کر دیا.حالانکہ اس
وقت حضرت ابو بکر کے اپنے صاحبزادے اور دیگر اعزہ واقارب کثرت کے ساتھ موجود تھے.اب ہر شخص
سمجھ سکتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے کہ اسے ہرگز مشورہ اور انتخاب کی روح کے منافی نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ
اول تو حضرت ابو بکڑ نے یہ فیصلہ خود بخود نہیں کیا بلکہ اہل الرائے صحابہ کے مشورہ کے بعد کیا تھا.دوسرے
حضرت ابوبکر خود ایک منتخب شدہ خلیفہ تھے جس کی وجہ سے گویا ان کا ہر فیصلہ قوم کی آواز کا رنگ رکھتا تھا اور
پھر انہوں نے اپنے کسی عزیز کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ ایک بالکل غیر شخص کو خلیفہ بنایا جس کے معاملہ میں یہ
امکان نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگ خلیفہ وقت کی قرابت کا لحاظ کر کے مشورہ میں کمزوری دکھا ئیں گے.اس
صورت میں ہرگز یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ مشورہ اور انتخاب کے طریق کو توڑا گیا ہے بلکہ یہ صورت بھی درحقیقت
مشورہ کی ایک قسم کبھی جائے گی.علاوہ ازیں حضرت عمر کی خلافت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک صریح پیشگوئی بھی تھی.تے جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو ان کی خلافت پر اعتراض نہیں ہوسکتا تھا اور
نہ ہوا بلکہ سب نے کمال انشراح کے ساتھ اسے قبول کیا.دوسرا سوال حضرت عثمان کی خلافت کا ہے.سو اول تو ان کا انتخاب خودمحد ودمشورہ سے ہی ہوا ہو مگر
بہر حال وہ بطریق مشورہ تھا.اور ان کی خلافت کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ سابقہ خلیفہ کے حکم سے
قائم ہوئی تھی اور چونکہ اسلام نے مشورہ اور انتخاب کے طریق کی تفاصیل میں دخل نہیں دیا بلکہ تفاصیل کے
تصفیہ کو وقتی حالات پر چھوڑ دیا ہے اس لئے محدود مشورہ کا طریق جو حضرت عثمان کی خلافت کے متعلق
اختیار کیا گیا وہ ہرگز اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں سمجھا جاسکتا.خصوصاً جبکہ اس بات کو بھی مدنظر رکھا جاوے
طبری و تاریخ کامل ابن اثیر حالات ۱۳ نیز موطا مالک بحوالہ تلخیص الصحاح باب في ذكر الخلفاء الراشدين
بخاری و مسلم ابواب فضائل اصحاب فضائل حضرت عمر
: بخاری کتاب فضائل اصحاب باب قصہ البیعتہ والا تفاق علی عثمان عن عمرو بن میمون.نیز بخاری ومسلم عن معدان بن
ابی طلحه و بخاری و مسلم وابوداؤ دوتر مندی عن ابن عمر بحوالہ تلخیص الصحاح باب في ذكر الخلفاء الراشدين
Page 733
ZIA
کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے جو اس شوری کے صدر تھے جس نے حضرت عثمان کی خلافت کا فیصلہ کیا
اپنے طور پر بہت سے اہل الرائے صحابہ سے مشورہ کر لیا تھا اور رائے عامہ کوٹو لنے کے بعد خلافت کا فیصلہ کیا
گیا تھا.اور پھر یہ کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ اگر اس معاملہ کو کھلے طریق پر رائے عامہ پر چھوڑا جاتا تو
ممکن تھا کہ کوئی فتنہ کی صورت پیدا ہو جاتی.علاوہ ازیں حضرت عمرؓ نے یہ بھی تصریح کردی تھی کہ گو میرے
لڑکے کو مشورہ میں شامل کیا جاوے مگر اسے خلافت کا حق نہیں ہو گا.پھر یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ حضرت
عمرہ کی طرح حضرت عثمان کی خلافت کے متعلق بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی.اس لئے
ان کی خلافت پر کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوا.بنوامیہ کی خلافت صحیح اسلامی خلافت نہ تھی اب
رہا ملوک بنوامیہ اور بنوعباس کا سوال.سوان
کا طریق خلافت واقعی اسلامی طریق کے خلاف تھا
اور محققین اسلام نے کبھی بھی ان کی امارت کو اسلامی طریق کی امارت نہیں سمجھا اس لئے وہ قابل حجت نہیں
ہے.تاریخ و حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ جب امیر معاویہ نے بعض غلط مشوروں میں آکر
پہلی دفعہ اسلام میں یہ بدعت جاری کرنی چاہی یعنی جمہور سے حق انتخاب عملاً چھین کر اپنے بیٹے یزید کو اپنی
زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کر دینا چاہا تو ان کبار صحابہ میں سے اکثر نے جو اس وقت زندہ تھے ان کی
مخالفت کی اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ طریق اسلامی تعلیم کے خلاف ہے کہ خلیفہ کی زندگی میں ہی اس کے
بیٹے کے لئے بیعت کا عہد لیا جا رہا ہے.مگر امیر معاویہ نے نہ مانا اور عوام کا سہارا ڈھونڈ کر یزید کو اپنا
جانشین مقرر کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امیر معاویہ فوت ہو گئے تو جو تھوڑے بہت صحابہ اس وقت بقید
حیات تھے وہ گوفتنہ کے خیال سے خاموش رہے مگر جیسا کہ تاریخ و حدیث میں اشارے ملتے ہیں انہوں نے
دل میں یزید کی امارت کو قبول نہیں کیا بلکہ حضرت امام حسینؓ اور عبد اللہ بن زبیر نے تو اس طریق کو
اسلامی تعلیم کے اس قدر خلاف سمجھا کہ باوجود نہایت درجہ کمزوری کی حالت میں ہونے کے وہ یزید کے مقابلہ
کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین تو یزید کے زمانہ میں ہی اور عبد اللہ بن زبیر
بخاری کتاب الاحکام باب كَيْفَ يُبَايَعُ الْإِمَامُ - نیز طبری و تاریخ کامل حالات استخلاف حضرت عثمان
بخاری کتاب فضائل باب قصته البيعة عن عمرو بن میمون
سی : مسلم باب من فضائل عثمان وستر مندی بحوالہ مشکوۃ باب مناقب عثمان
بخاری تفسیر سورۃ احقاف و فتح الباری جلد ۸ صفحه ۴۴۲ و ۴۴۳ نیز تاریخ کامل جلد ۳ صفحه ۲۱۴ تا ۲۱۸ وطبری حالات ۵۵۶
Page 734
واء
کچھ عرصہ بعد شہید ہو گئے.مگر انہوں نے اس استبدادی حکومت کے سامنے جسے وہ اسلامی طریق کے
خلاف سمجھتے تھے گردن نہیں جھکائی.لیکن امیر معاویہ کی یہ غلطی بعد میں آنے والوں کے لئے ایک مثال بن
گئی اور اس وقت سے بادشاہی رنگ میں ولی عہدی کا طریق جاری ہو گیا.اس بات کا ثبوت کہ امیر معاویہ اور ان کے بعد آنے والے امراء کی امارت صحیح اسلامی خلافت
نہیں تھی بلکہ صرف ایک بادشاہت تھی اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد صحیح اسلامی خلافت صرف تمہیں سال رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت کا
طریق جاری ہو جائے گا.اور اگر حساب کیا جاوے تو حضرت علی یا امام حسنؓ کی خلافت تک یہ تمہیں سالہ
میعاد پوری ہو جاتی ہے اور امیر معاویہ کے زمانہ سے وہ میعاد شروع ہوتی ہے جسے بادشاہت کے نام
سے موسوم کیا گیا ہے.جانشین مقرر کرنے کی شرائط خلاصہ کلام یہ کہ اصل اسلامی تعلیم اور صحیح اسلامی تعامل یہی ہے کہ
کی
خلافت و امارت کا قیام لوگوں کے مشورہ سے ہونا چاہئے جیسا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ کے معاملہ میں ہوا.لیکن اگر کوئی خلیفہ اپنا
جانشین خود مقرر کر جانے کی ضرورت محسوس کرے تو بعض حالات میں اس طریق کے اختیار کرنے کی
اجازت تو ہے مگر جیسا کہ اسلامی تعلیم کی روح اور خلفاء اربعہ کی سنت سے ثابت ہوتا ہے اس کے لئے
پانچ شرطیں ضروری ہیں اول یہ کہ اس وقت کوئی ایسے خاص حالات موجود ہونے چاہئیں جن کی وجہ سے
عام طریق کو چھوڑ کر اس طریق کا اختیار کرنا مناسب ہو.دوم یہ کہ جانشین کا تقر ر لوگوں کے مشورہ
کے ساتھ کیا جاوے.سوم یہ کہ یہ تقر ر صرف آئندہ خلیفہ یا امیر تک محمد ودر ہے.یہ نہیں کہ کوئی خلیفہ یہ
حکم دے جاوے کہ میرے بعد فلاں شخص امیر ہو اور اس کے بعد فلاں اور اس کے بعد فلاں کیونکہ یہ
طریق آئندہ آنے والی نسلوں سے حق انتخاب چھین لینے کے مترادف ہے.چہارم یہ کہ یہ جانشین
خلیفہ وقت کے قریبی رشتہ داروں میں سے نہ ہو.ہم یہ کہ جانشین مقرر کرنے والا خلیفه خود منتخب شدہ
خلیفہ ہونا چاہئے.واللہ اعلم
طبری تاریخ کامل ابن اثیر حالات ۶۰ ھ وا۶ ھ و نیز حالات خلافت ابن زبیر
ترندی وابوداؤ دو بحوالہ مشکوة كتاب الفتن فصل ثانى عن سفينة
سے : بخاری و مسلم وغیرہ عن ابن عمر بحوالہ تلخیص باب فی ذکر خلفاء الراشدین
Page 735
۷۲۰
کیا امارت سے دستبرداری کی جاسکتی ہے؟ یہ سوال کہ کوئی خلیفہ یا امیر با قاعدہ طور پر منتخب
یا مقرر ہونے کے بعد خود بعد میں کسی مصلحت کی
بنا پر خلافت سے دست بردار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ایک ایسا سوال ہے جس کے متعلق اسلامی شریعت میں
کوئی نص نہیں پائی جاتی مگر ظاہر ہے کہ اس معاملہ میں دنیوی امراء کے متعلق تو کوئی امر مانع نہیں
سمجھا جاسکتا.البتہ دینی خلفاء کا سوال قابل غور ہے.تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ جب حضرت عثمان خلیفہ ثالث
سے ان کے زمانہ کے باغیوں نے یہ درخواست کی کہ آپ خود بخو دخلافت سے دست بردار ہوجائیں ورنہ
ہم آپ کو جبراً الگ کر دیں گے یا قتل کر دیں گے تو اس پر حضرت عثمان نے یہ جواب دیا کہ جو عزت کی
قمیص خدا نے مجھے پہنائی ہے میں اسے خود اپنی مرضی سے کبھی نہیں اتاروں
گا یا جس میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف اشارہ تھا جو آپ نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ خدا تمہیں ایک قمیص
پہنائے گا اور لوگ اسے اتارنا چاہیں گے مگر تم اسے نہ اتارنا ہے لیکن اس کے مقابلہ میں حضرت امام حسنؓ
کا یہ فعل ہے کہ انہوں نے امت محمدیہ کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے
دستبرداری اختیار کرلی.اور روایت آتی ہے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی
کہ میرے اس نواسے کے ذریعہ خداد و مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا.گویا امام حسن کے اس فعل کو
مقام مدح میں سمجھا گیا ہے کہ ان کی اس دست برداری کے نتیجہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی
پوری ہوئی جس میں آپ نے امام حسنؓ کی ایک امتیازی خوبی بیان کی تھی اور امت محمدیہ پھر ایک نقطہ پر جمع
ہوگئی.ان دو مثالوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دست برداری کا سوال حالات پر چھوڑا گیا ہے یعنی یہ کہ
اگر خلافت کا استحکام ہو چکا ہو جیسا کہ حضرت عثمان کے معاملہ میں ہو چکا تھا یا یہ کہ اگر دست برداری کے
متعلق لوگوں کی طرف سے خواہش یا مطالبہ ہو تو وہ نا پسندیدہ بلکہ نا جائز ہے.لیکن اگر قبل استحکام خلافت
جیسا کہ امام حسنؓ کے معاملہ میں پایا جاتا ہے کسی اعلیٰ غرض کے حصول کے لئے خود خلیفہ اپنی خوشی سے اپنی
خلافت سے دست بردار ہو جانا مناسب خیال کرے تو اس کے لئے کوئی امر مانع نہیں ہے.اس جگہ یہ
: طبری و تاریخ کامل ابن اثیر حالات قتل حضرت عثمان نیز زرین عن عبداللہ بن سلام بحوالہ تلخیص الصحاح باب فی
ذكر الخلفاء الراشدين
ترندی بحوالہ مشکوۃ باب مناقب عثمان
۳ : بخاری عن حسن بصری کتاب الصلح نیز طبری و تاریخ کامل ابن اثیر حالات ۴۱ ہجری
۴ : بخاری بحوالہ مشکوۃ باب مناقب اہل بیت و فتح الباری شرح حدیث مذکور
Page 736
۷۲۱
ذکر ضروری ہے کہ یہ خیال جو ہم نے یہاں ظاہر کیا ہے یہ اسلام کا کوئی فیصلہ شدہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ محض
ایک رائے ہے جو واقعات سے نتیجہ نکال کر قائم کی گئی ہے.واللہ اعلم
عزل اور میعادی انتخاب کا سوال یہ سوال کہ آیا امیر یا خلیفہ کا انتخاب میعادی بھی ہوسکتا ہے
یا نہیں؟ نیز یہ کہ آیا کوئی شخص امیر یا خلیفہ منتخب ہونے کے کسی
اور دینی اور دنیوی امراء میں فرق نقص یا کمزوری کی وجہ سے اپنے عہدہ سے معزول بھی ہوسکتا
ہے یا نہیں؟ ایک نہایت قابل غور سوال ہے.اس معاملہ میں اسلام نے دینی اور دنیاوی امراء میں ایک
امتیاز رکھا ہے.دینی امراء سے مراد وہ امراء ہیں جن کے ہاتھ میں دینی سیاست یا دینی اور دنیوی سیاست
مخلوط طور پر ہو اور دنیوی امراء سے وہ امراء مراد ہیں جن کا تعلق محض دنیوی سیاست کے ساتھ ہو.اوّل الذکر امراء کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے.وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
آمَنَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيكَ هُمُ الْفُسِقُوْنَO یعنی
”اے مومنو! اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے (اعلیٰ) ایمان لائیں اور (اعلیٰ
قسم کے ) نیک اعمال کریں کہ ضرور انہیں دنیا میں خلیفہ مقرر کرے گا جیسا کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو
خلیفہ بنایا اور اللہ ان خلفاء کے دین کو جو اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے ان کے ذریعہ سے طاقت وقوت
عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا یہ لوگ ہمیشہ میری عبادت کریں گے اور
میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے اور جو لوگ ان خلفاء کی اطاعت سے منحرف ہوں گے وہ
بد عہد اور باغی سمجھے جائیں گے.اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ دینی خلفاء کی خلافت خدا تعالیٰ کے
خاص تصرف اور خاص منشا کے ماتحت قائم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ان کے شامل حال
رہتی ہے اور ان کے ذریعہ سے دینی سیاست کی تقویت اور مضبوطی مقصود ہوتی ہے اور اسی لئے ان کی
اطاعت سے خارج ہونے والا شخص خدا کی نظر میں فاسق و باغی سمجھا جاتا ہے.اس آیت کی عملی تشریح
میں ایک حدیث آتی ہے کہ :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ
: سورۃ نور : ۵۶
Page 737
۷۲۲
أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَابْنِهِ حَتَّى اَكْتُبَ كِتَابًا فَأَعْهَدُ أَنْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنَّوْنَ وَيَقُولُ
قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى ثُمَّ قُلْتُ يَأْبَى اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ اَوْيَدْفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ
یعنی حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ جس مرض میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس کے
ابتدا میں آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے باپ اور بھائی کو بلا کر ابو بکر کی خلافت
کے متعلق وصیت کر جاؤں تا کہ میرے بعد کوئی دوسرا شخص خلافت کی تمنا میں کھڑا نہ ہو جاوے اور یہ دعوی نہ
کر دے کہ میں ابوبکر کی نسبت خلافت کا زیادہ حق دار ہوں مگر پھر میں نے اس خیال سے یہ ارادہ ترک
کر دیا کہ مومنوں کی جماعت ابو بکر کے سوا کسی اور شخص کی خلافت پر رضامند نہ ہوگی اور نہ ہی خدا کسی
اور شخص کی خلافت کو قائم ہونے دے گا.اس حدیث سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ گودینی
خلفاء کا انتخاب بظاہر لوگوں کے مشورہ سے ہوتا ہے مگر در حقیقت ان کے انتخاب میں خدا کا دست غیبی کام
کرتا ہے اور یہی اسلامی خلافت کا سچا فلسفہ ہے کہ بظاہر انتخاب مومن کرتے ہیں مگر حقیقتا تصرف خدا کا ہوتا
ہے یعنی ایک مرسل و مامور کی بعثت کے زمانہ کی طرح خدا خود تو سامنے نہیں آتا مگر اس کی مخفی تاریں لوگوں
کے قلوب
کو کھینچ کھینچ کر خلافت کے اہل شخص کی طرف مائل کر دیتی ہیں.اندریں حالات دینی خلفاء کے
متعلق خواہ ان کا انتخاب بظاہر مشورہ ہی کے طریق پر ہوتا ہے.میعادی انتخاب کا سوال یا انتخاب کے بعد
عزل کا سوال بالکل خارج از بحث ہے اور اسی لئے خدا نے ایسے خلفاء کی اطاعت میں داخل نہ ہونے
والوں یا داخل ہو کر اطاعت سے خارج ہونے والوں کو باغی قرار دیا ہے اور عقلاً بھی غور کیا جاوے تو دینی
خلفاء کا انتخاب میعادی نہیں ہونا چاہئے اور نہ انتخاب کے بعد ان کے عزل کا سوال اٹھنا چاہئے کیونکہ
دینی تعلق کی بنیا د عقیدت اور اخلاص پر ہوتی ہے اور دینی خلیفہ امام کا مرتبہ رکھتا ہے اور گو وہ احکام شریعت
کے ماتحت ہوتا ہے اور ان میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کا حق نہیں رکھتا مگر شریعت کی تشریح اور نفاذ کا کام
اسی سے تعلق رکھتا ہے اور دینی سیاست کلیتا اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اعمال میں بھی وہ امت کے لئے
گویا ایک نمونہ سمجھا جاتا ہے.پس اس قسم کے روحانی تعلق کو میعادی قرار دینا یا لوگوں کے لئے ایسے تعلق
:
بخاری کتاب الاحکام باب الاستخلاف مسلم باب من فضائل ابی بکر مخلوطاً
آج کل کی سیاسی اصطلاحات کی رو سے کہہ سکتے ہیں کہ گویا اس معاملہ میں خدا تعالیٰ وائر پلر
(WIREWPULLER) کا کام دیتا ہے
Page 738
۷۲۳
کے قطع کر دینے کو جائز کر دینا مذہب کی روح کے بالکل منافی ہے اور اس کے نتیجہ میں روحانی تعلق اور صلحاء
کی بیعت و صحبت کی غرض و غایت بالکل فوت ہو جاتی ہے اور مذہب میں ایک ایسی ناجائز آزادی کا دروازہ
کھل جاتا ہے جس کا آخری نتیجہ سوائے لامذہبی اور بے دینی کے اور کچھ نہیں.لیکن اس کے مقابلہ میں دنیوی امراء کا معاملہ بالکل جدا گانہ ہے.ان کے تعلق کی بنیا د عقیدت واخلاص
پر
نہیں ہوتی بلکہ محض سیاسی مصالح پر ہوتی ہے اور نہ ان کے میعادی انتخاب یا عزل سے کوئی براہ راست
دینی فتنہ پیدا ہوتا ہے.اس لئے محض سیاسی حکام کے متعلق اسلام نے کوئی خاص پابندی عائد نہیں کی یعنی
اس معاملہ میں لوگ آزا در کھے گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے حالات کے ماتحت ضروری خیال کریں تو سیاسی
حکام کے انتخاب کو میعادی کر دیں یا اگر انتہائی حالات کے پیدا ہو جانے پر ضروری سمجھیں تو مناسب طریق پر
ان کے عزل کے لئے ساعی ہوں.اسلامی اطاعت کا میعار لیکن چونکہ اسلام فتنوں کے سد باب اور امن کے قیام کا نہایت زبر دست
حامی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں اس بات
پر بہت زور دیا گیا ہے کہ خروج عن الطاعت اور عزل کا سوال سوائے انتہائی حالات کے نہیں اٹھنا چاہئے
ا
اور لوگوں کے لئے لازم ہے کہ حتی الوسع اپنے امیر کی فرمانبرداری اور اطاعت کے طریق سے خارج
ہونے کا خیال دل میں نہ لائیں بلکہ اس معاملہ میں یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہئے کہ اپنے حقوق کو غصب ہوتا دیکھ کر بھی صبر سے کام لیں.اور اپنے امراء
کی طرف سے ظلم اور تعدی تک برداشت کریں مگر بغاوت اور تفرقہ کے راستے پر قدم زن نہ ہوں.چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سَتَرَوْنَ بَعْدِى أَثَرَةً وَّامُورًا تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا
يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ یعنی اے مسلمانو! میرے بعد
ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم پر ایسے ایسے لوگ امیر بنیں گے جو تمہارے حقوق غصب کریں گے اور ایسی ایسی
باتیں کریں گے جو بہت ناپسندیدہ ہوں گی اور تمہیں اوپری لگیں گی.صحابہ نے عرض کیا تو پھر یا رسول اللہ !
ایسے حالات میں آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں.آپ نے فرمایا تم اپنے امیروں کے حقوق انہیں ادا کرو اور
اپنے حقوق خدا سے مانگو.“
پھر فرماتے ہیں:
بخاری کتاب الفتن باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سَتَرَوْنَ بَعْدِى
Page 739
۷۲۴
مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةٌ لا یعنی ” جو شخص امیر کی
اطاعت سے خروج کرتا ہے اور جماعت کے اتحاد سے علیحدگی اختیار کر کے تفرقہ کی بنیاد قائم کرتا ہے.وہ اگر بغیر تو بہ کے اسی حالت میں مرجاوے تو اس کی موت غیر اسلامی موت ہوگی، مگر ساتھ ہی رعایا کو یہ
تحریک کی گئی ہے کہ اگر امیر کا رویہ ظالمانہ اور غاصبانہ ہو تو وہ اسے نیک مشورہ دے کر اصلاح کی کوشش
کرے اور اس کوشش کو اسلام میں ایک بہت بڑا جہاد اور نیکی کا فعل قرار دیا گیا ہے چنانچہ فرمایا:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ے یعنی ” جب کوئی امیر ظلم و تعدی
کا طریق اختیار کرے تو اس حالت میں سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اس امیر کوحق وانصاف
کا مشورہ دے کر اسے اس کی ناجائز اور ظالمانہ کارروائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرے.“
66
لیکن اگر اس پر بھی امیر کی اصلاح نہ ہو اور وہ اپنی نا واجب کا رروائیوں پر مصرر ہے اور صریح طور پر
خدائی احکام کے خلاف حکم دے تو رعایا کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ نیک اور جائز باتوں میں تو بدستور امیر کی
اطاعت کرتی رہے مگر نا جائز حصہ میں اس کی اطاعت سے انکار کر دے چنانچہ فرمایا:
السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ وَمَالَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا
أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ یعنی ” ہر مسلمان پر اپنے امیر کا حکم ماننا فرض ہے خواہ وہ حکم
اسے پسند ہو یا نہ ہو لیکن اگر اسے کوئی ایسا حکم دیا جاوے جس میں خدائی قانون کی صریح نافرمانی لازم آتی
ہو تو ایسے حکم کا سنا اور ماننا اس پر فرض نہیں ہوگا.“
اگر با وجود رعایا کے اس نیک مشورہ اور اس جزوی عدم اطاعت کے کسی امیر کے ناجائز احکام کا
سلسلہ ترقی کرتا جاوے اور وہ بر ملا طور پر خدائی قانون سیاست اور خدائی قانون شریعت کے خلاف
قدم زن ہونا شروع کر دے حتی کہ اس کی امارت اس حد تک ضرر رساں صورت اختیار کر لے کہ
اسے توڑنے کے لیے ملک کے امن اور جماعت کے اتحاد تک کو خطرے میں ڈالنا مناسب ہو جاوے تو
اس قسم کے انتہائی حالات میں لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس امیر کی اطاعت سے خروج کر کے
اس کے عزل کے لیے ساعی ہوں چنانچہ حدیث میں آتا ہے:
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعَ وَالطَّاعَةِ
مسلم بحوالہ مشکوۃ کتاب الامارۃ فصل اول
س : بخاری کتاب الاحکام باب السمع والطاعة
ترندی و ابوداؤ د واحمد بروایت مشکوۃ باب الامارة
Page 740
۷۲۵
فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوُا
كُفْرًا بَوَّاحًا عِنْدَ كُمُ مِنَ اللهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی عبادۃ بن
صامت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت میں یہ اقرار لیا کرتے تھے کہ ہم
ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کریں گے.عسر میں اور میسر میں.پسندیدگی کی حالت میں اور نا پسندیدگی
کی حالت میں خواہ ہمارے حقوق ہمیں ملیں یا ہم سے چھینے جائیں اور یہ کہ ہم کسی حالت میں بھی اپنے امیروں
کے ساتھ امارت کے معاملہ میں تنازعہ نہیں کریں گے.مگر آپ نے فرمایا ”ہاں اگر تم اپنے امیر کے رویہ
میں کوئی ایسا کھلا کھلا کفر پاؤ یعنی خدا کے کسی اصولی قانون کی ایسی صریح نافرمانی دیکھو جس کے متعلق
تمہارے پاس خدا کی طرف سے کوئی روشن اور قطعی دلیل موجود ہو، تو پھر تمہیں اس کے ساتھ امارت کے
معاملہ میں تنازعہ کرنے کا حق ہے.اس حدیث میں جو کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے متعلق یا درکھنا
چاہئے کہ اس سے صرف عقیدہ کا کفر مراد نہیں بلکہ قانون سیاست اور قانون شریعت کے کسی اصل الاصول کا
تو ڑ نا مراد ہے.چنانچہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کسی بے گناہ مسلمان کا ناجائز قتل بھی کفر میں داخل
ہے.اور محقق صحابہ نے ان خلاف شریعت کا رروائیوں کو بھی جو حضرت عثمان کے زمانہ میں فتنہ پردازوں
کی طرف سے شروع ہو گئی تھیں کفر قرار دیا ہے.مگر امیر کے خلاف سراٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ
کفر بالکل صریح اور کھلا کھلا ہو اور کسی اجتہادی غلطی یا مشتبہ حالات کا نتیجہ نہ ہو.حتی کہ امیر کی بریت کے
لیے امکانی طور پر بھی تاویل کا کوئی دروازہ کھلا نہ رہے اور اسکی امارت اس حد تک خطر ناک صورت اختیار کر
لے کہ اس کے توڑنے کے لیے ملک کے امن اور قوم کے اتحاد تک کو خطرے میں ڈالناضروری ہو جاوے.عزل کی کوشش حکومت کے اندر رہتے ہوئے جائز نہیں لیکن اس حالت میں بھی اسلام
اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ امیر
کی مملکت میں رہتے ہوئے اور اس کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھتے ہوئے اس کے خلاف بغاوت کا
جھنڈا بلند کیا جاوے اور اس میں غرض یہ مد نظر ہے کہ تا ملک کے اندرسول وار یعنی خانہ جنگی کی صورت پیدا
نہ ہو اور یہ خطر ناک منظر نظر نہ آوے کہ ایک امیر کے ماتحت رہتے ہوئے لوگ اس کے خلاف سراٹھاتے
بخاری کتاب الفتن ومسلم كتاب الامارة
ے : بخاری کتاب الفتن باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا
بخاری کتاب الفتن باب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا
Page 741
۷۲۶
ہیں.چنا نچہ اس قسم کے انتہائی حالات میں اسلامی طریق یہ ہے کہ جولوگ امیر کی حکومت کو از بس خطر ناک
سمجھیں انہیں چاہئے کہ اس کی مملکت سے نکل جائیں اور مملکت سے نکل جانے کے بعد اگر ضروری اور
مناسب خیال کریں تو اس کے عزل کے لیے ساعی ہوں.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی
اسی اصل کے ماتحت وقوع میں آئی تھی کہ آپ نے مکہ کی حکومت کے مظالم اور مذہبی دست درازیوں سے
تنگ آکر بالآخر رؤساء قریش کی حکومت سے خروج کا طریق اختیار کیا تھا.اور پھر اس کے بعد خدا نے
آپ کے ذریعہ قریش کی اس ظالمانہ حکومت کے توڑنے کی تدبیر فرمائی تھی اور قریباً یہی صورت خدائی
حکومت کے ماتحت بنو اسرائیل نے فرعون کے مظالم پر اختیار کی تھی.یعنی یہ کہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ
ہو کر فرعون کی حکومت سے نکل گئے تھے.اور اسی صورت سے ملتی جلتی صورت امام حسین اور عبد اللہ بن
زبیر نے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی امارت کے موقع پر اختیار کی تھی.یعنی جب امیر معاویہ نے بعض
غلط مشوروں میں آکر خلاف تعلیم اسلام اور خلاف سنت خلفاء الراشدین اپنی زندگی میں ہی اپنے لڑکے
یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہا تو ان اصحاب نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ طریق خلاف تعلیم اسلام ہے
لیکن جب امیر معاویہ نے ان کی رائے نہ مانی اور عوام کا سہارا ڈھونڈ کر یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا
تو انہوں نے ناچار خاموشی اختیار کی.کیونکہ اس وقت امیر معاویہ برسر حکومت تھے اور یہ اصحاب ان کی
بیعت اطاعت میں داخل تھے اس لیے ان کے لیے امیر معاویہ کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ان کے
خلاف سراٹھا نا جائز نہیں تھا اور دوسری طرف اس وقت امیر معاویہ کی حکومت سے باہر نکل جانے کی بھی کوئی
عملی صورت نہیں تھی.لیکن جب امیر معاویہ فوت ہو گئے.اور یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اس
وقت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر اس کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے
ہوئے ہے کیونکہ ابھی یزید کی اطاعت ان پر فرض نہیں ہوئی تھی.اس صورت میں گویا یزید کے خلاف اٹھنا
یزید کی مملکت سے باہر ہو کر مقابلہ کرنے کے مترادف تھا مگر امام حسین اور عبد اللہ بن زبیر کی یہ کوشش کوئی
مستقل نتیجہ نہیں پیدا کرسکی اور بنو امیہ کی استبدادی حکومت کو فروغ حاصل ہو گیا.بہر حال اسلام میں کسی
امیر کے ماتحت رہتے ہوئے اس کے خلاف سراٹھانے اور اس کے عزل کی کوشش کرنے کو پسند نہیں کیا گیا
بلکہ اس صورت میں اسلامی طریق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امیر کے رویہ کو صریح طور پر خلاف اصول سیاست
سورة طه : ۷۸ وسورة يونس: ۹۱،۸۸
طبری حالات ۶۰ ھ وا ۶ ہجری نیز تاریخ کامل جلد ۳ صفحه ۲۱۴ تا ۲۱۸ وجلد ۴ صفحه ۷،۶
Page 742
۷۲۷
پائے اور اس کی امارت کو اس حد تک ضرر رساں سمجھے کہ اس کے توڑنے کے لیے ملک کے امن اور جماعت
کے اتحاد تک کو خطرے میں ڈالنا ضروری خیال کرے تو اسے چاہیے کہ ایسے امیر کی مملکت سے باہر نکل
جاوے اور پھر جس طرح مناسب ہو اس کے عزل کے لیے ساعی ہو.اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی امیر لوگوں
کو باہر نکل جانے سے جبر اردو کے تو پھر کیا طریق
اختیار کیا جاوے تو اس کا یہ جواب ہے کہ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اصولی طور پر فرماتا ہے کہ
لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ل یعنی انسان صرف اس حد تک مکلف ہے جس حد تک اس کی
طاقت ہے اور جیسا کہ بنی اسرائیل کے واقعہ میں خدائی اشارہ پایا جاتا ہے جہاں خدا فرما تا ہے کہ فرعون کا
بنی اسرائیل کے تعاقب میں جا کر ان کو خروج سے جبراً روکنے کی کوشش کرنا نا جائز اور خدائی قانون سے
بغاوت کے ہم معنی تھا.اس قسم کی صورت میں جو خود امیر کی طرف سے پیدا کی جاوے ملک کے اندر رہتے
ہوئے بھی ظالم امیر کے خلاف سراٹھانا جائز سمجھا جائے گا.کیا امارت کا حق صرف قریش کے ساتھ مخصوص ہے؟ اسلامی اصول حکومت کی بحث کی ضمن
میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا
اسلامی تعلیم کی رو سے خلیفہ یا امیر کے لیے کسی خاص قوم میں سے ہونا تو ضروری نہیں ہے؟ یہ سوال
خصوصیت سے اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ بعض احادیث میں یہ مذکور ہوا ہے کہ خلفاء قریش میں سے ہوں گے
جس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ گویا خلیفہ یا امیر کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے مگر یہ خیال
بالکل غلط اور بے بنیاد ہے.پہلی دلیل جو اس بات کو غلط ثابت کرتی ہے یہ ہے کہ اسلام میں اصولاً قومی یا
نسلی خصوصیات کو دینی یا سیاسی حقوق کی بنیاد نہیں تسلیم کیا گیا.بالفاظ دیگر اسلام میں ان معنوں کے لحاظ
سے کوئی ذاتیں نہیں کہ فلاں ذات کو یہ حقوق حاصل ہوں گے اور فلاں کو یہ بلکہ اس میں ذاتوں اور قوموں
کو صرف تعارف اور شناخت کا ایک ذریعہ رکھا گیا ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں.چنانچہ قرآن شریف
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ يَكُونُوا
خَيْرًا مِنْهُمْ وَ جَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنفُسِكُمْ
یعنی اے مسلمانو! تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر اپنی بڑائی بیان کرے یا دوسری
: سورة بقره : ۲۸۷
: سورة حجرات : ۱۴
: سورۃ یونس : ۹۱
: سورة حجرات : ۱۲
Page 743
۷۲۸
قوم کو اپنے سے نیچا سمجھے کیونکہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ خدا کی نظروں میں کون بڑا ہے.اور ہم نے جو تمہیں
دنیا میں قوموں اور قبائل کی صورت میں بنایا ہے تو اس کی غرض صرف یہ ہے کہ تم آپس کی شناخت اور تمیز
میں آسانی پاؤ.یہ نہیں کہ تم اس تفریق پر کسی قسم کی بڑائی یا خاص حقوق کی بنیاد سمجھو کیونکہ خدا کی نظر میں تم
میں سے بڑا وہ ہے جو خدائی قانون کی زیادہ اطاعت اختیار کرتا ہے خواہ وہ کوئی ہو‘“
اس واضح اور غیر مشکوک اصولی تعلیم کے علاوہ قرآن شریف خاص خلافت و امارت کے سوال میں بھی
قومی یا خاندانی حق کے خیال کو رد کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ
اَنْ تُؤَدُّوا الْآمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ یعنی
خدا تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ حکومت کی باگ ڈور صرف اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو (خواہ وہ کوئی ہو )
اور جو لوگ امیر منتخب ہوں انہیں چاہیے کہ اپنی حکومت کو عدل و انصاف کے ساتھ چلائیں.“ اس آیت میں
خلیفہ یا امیر کے لیے صرف یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ حکومت کا اہل ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہیں
لگائی گئی جو اس بات کی یقینی دلیل ہے کہ اسلام میں خلیفہ یا امیر کے لیے اہلیت کے سوا کوئی شرط نہیں ہے.اسی طرح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ
عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِی - یعنی حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانو! اگر تم پر ایک حبشی غلام بھی امیر بنایا جاوے تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی
اطاعت کرو.اگر اسلام میں امیر کا قریشی ہونا ضروری تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بے معنی
قرار پاتا ہے بلکہ اس صورت میں آپ کو یہ فرمانا چاہئے تھا کہ تم ہر قریشی امیر کی فرمانبرداری کرو خواہ وہ
کیسا ہی ہو.الغرض کیا بلحاظ اصول کے اور کیا بلحاظ تخصیص کے یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ
اسلام میں حکومت اور خلافت کو کسی خاص قوم کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے اور اسلامی تعلیم کی روح اس
خیال
کو دور سے دھکے دیتی ہے.اب رہا یہ سوال کہ پھر ان احادیث کا مطلب کیا ہے جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خلفاء اور
ائمہ قریش میں سے ہوں گے.سوان احادیث پر ایک ادنی تدبر بھی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی
ہے کہ یہ ایک پیشگوئی تھی نہ کہ حکم یا سفارش.یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بخاری کتاب الاحکام باب السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
ا: سورۃ نساء : ۵۹
Page 744
۷۲۹
ذریعہ اور بہت سی باتوں کا اظہار فرمایا تھا جو آئندہ ہونے والی تھیں اسی طرح جو خلفاء آپ کے بعد ہونے
والے تھے ان کے متعلق آپ کو یہ علم دیا گیا تھا کہ وہ قبیلہ قریش میں سے ہوں گے اور پیشگوئی کی صورت
میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں رہتا کیونکہ بہر حال خلفاء نے کسی نہ کسی قوم یا قبیلہ میں سے ہونا تھا اور اگر اس
وقت کے حالات کے ماتحت وہ سب کے سب قریش میں سے ہوئے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوسکتا.علاوہ ازیں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اس زمانہ کے حالات کے ماتحت قریش ہی وہ قبیلہ تھا جو حکومت کی
سب سے زیادہ اہلیت رکھتا تھا.کیونکہ اول تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ تھا جس کی وجہ سے
طبعا اسے مسلمانوں میں ایک جائز عزت حاصل تھی اور لوگ اس کے اثر کو قبول کرتے تھے.دوم قریش کا
قبیلہ عرب کے سب سے زیادہ مرکزی شہر کا رہنے والا تھا اور وہی کعبتہ اللہ کا بھی متولی تھا جس کی وجہ سے
زمانہ جاہلیت میں بھی وہ سارے ملک میں خاص عزت واحترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور دوسرے
قبائل عرب عموماً ہر معاملہ میں قریش کی طرف دیکھتے تھے اور ان کی رہبری کو قبول کرتے تھے.سوم قریش
کے لوگ بوجہ اس نظام کے جو ان کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب نے مکہ میں جاری کیا تھا حکومت کے
نظام وطریق سے ایک حد تک واقف ہو چکے تھے اور ان کے سوا کوئی دوسرا قبیلہ امور حکومت سے آشنا
نہیں تھا.چہارم بوجہ اس کے کہ اسلام میں سابقین الاولین سب قریش میں سے تھے اور انہیں کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ
کی تعلیم کو اپنے اندر جذب کرنے کا سب سے زیادہ
موقع ملا تھا اس لیے وہ لازماً اسلامی طریق حکومت میں بھی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ اہلیت رکھتے
تھے.ان وجوہات کی بنا پر اس زمانہ میں قریش کو دوسرے قبائل عرب پر ایک حقیقی اور یقینی فوقیت حاصل
تھی اور انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلہ میں عنان حکومت کا جانا ملک کے لیے سخت ضرر رساں تھا اور یقیناً
کوئی دوسرا قبیلہ اس خیر و خوبی کے ساتھ نظام حکومت کو چلا نہ سکتا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد اسلام کے ابتدائی خلفاء نے چلایا مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسلام نے قریش کو ہمیشہ کے لیے
حکومت کا ٹھیکہ دے دیا تھا.چنانچہ اگر ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہوا ہے کہ
میرے بعد خلفاء وائمہ اسلام قریش میں سے ہوں گے تو دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ
بالآخر قریش حکومت کی اہلیت کو کھو بیٹھیں گے اور اسلام کی حکومت کو تباہ و برباد کرنے کا موجب بن
جائیں گے چنانچہ حدیث میں آتا ہے:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ
Page 745
۷۳۰
مِنْ قُرَيش - یعنی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری
امت کی تباہی بالآخر قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی.یعنی جب قریش کی حالت خراب
ہو جائے گی اور وہ حکومت کے اہل نہیں رہیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں حکومت کا رہنا بجائے
رحمت کے زحمت ہو جائے گا اور بالآخر قریش ہی کے ہاتھوں سے اسلامی حکومت کی تباہی کا سامان پیدا
ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا.اور یہ جو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے
تھے کہ قریش کی امارت قیامت تک رہے گی.اس سے بھی یہی مراد ہے کہ امت اسلامی کی تباہی تک
قریش بر سر حکومت رہیں گے اور پھر بالآخر انہیں کے ہاتھوں سے تباہی کا بیج بویا جا کر اسلام میں ایک نئے
دور کا آغاز ہو جائے گا.خلاصہ کلام یہ کہ قرآن واحادیث کے مجموعی مطالعہ سے یہ بات قطعی طور پر ثابت
ہوتی ہے کہ قریش کی امارت وخلافت کے متعلق جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس سے محض
پیشگوئی مراد ہے، حکم یا سفارش مراد نہیں اور پھر یہ پیشگوئی بھی میعادی اثر رکھتی تھی یعنی اسلام کے دور اول
کے ساتھ مخصوص تھی اور آپ کا منشاء یہ تھا کہ چونکہ اس وقت حکومت کی اہلیت سب سے زیادہ قریش میں
ہے اس لئے آپ کے بعد وہی بر سر حکومت واقتدار رہیں گے لیکن ایک عرصہ کے بعد وہ اس اہلیت کو
کھو بیٹھیں گے تو پھر اس وقت امت محمدیہ پر ایک انقلاب آئے گا اور اس کے بعد ایک نئے دور کی
داغ بیل قائم ہو جائے گی.الغرض یہ بات درست نہیں ہے کہ اسلام نے حکومت کے حق کو کسی خاص
خاندان یا قوم کے ساتھ محدود کر دیا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اسلام میں حکومت انتخاب سے قائم ہوتی ہے اور
انتخاب میں ہر شخص کے لئے دروازہ کھلا رکھا گیا ہے.یہ وہ مختصر ڈھانچہ حکومت کے طریق کا ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے اور ہر عقل مند اور غیر متعصب شخص
سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک بہترین ہدایت ہے جو اس معاملہ میں دی جاسکتی تھی کیونکہ اصول سیاست کے لحاظ
سے کامل ہونے کے علاوہ یہ تعلیم ایک ایسا جامع رنگ رکھتی ہے کہ تفاصیل کے مناسب اختلاف کے ساتھ وہ
ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے ایک شمع ہدایت کا کام دے سکتی ہے اور اس زمانہ کے ترقی یافتہ مغربی ممالک
کے سیاست دان بھی ابھی تک اصول سیاست میں اس سے بہتر طریق دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے.ظاہر ہے کہ سیاست کے بنیادی اصول چار ہیں.اول یہ کہ امیر یعنی صد ر حکومت کا تقررکس اصول پر
مبنی ہو.آیا ورثہ کے حق کی بنا پر یا کسی خاندانی حق کی بنا پر یا بعض خاص لوگوں کی رائے سے یا جمہور اور
بخاری کتاب الفتن اسلامی اصطلاح میں بڑے انقلاب کو بھی قیامت سے تعبیر کیا جاتا ہے
Page 746
۷۳۱
عامتہ الناس کے مشورہ کے ساتھ.دوسرے یہ کہ جب کوئی شخص امارت کے عہدہ پر قائم ہو جاوے تو
اس کا طریق حکومت کیا ہونا چاہئے آیا خود مختارانہ اور استبدادی یا کسی قانون کے ماتحت اور لوگوں کی رائے
اور مشورہ کے ساتھ.تیسرے یہ کہ لوگوں کا امیر کے متعلق کیا رویہ ہو.آیا وہ اس کے ساتھ انتہائی حد تک
تعاون اور اطاعت کا طریق اختیار کریں یا کہ ہر بات پر جو ان کی مرضی کے خلاف ہو بگڑیں اور اس کے
رستے میں روکیں ڈالیں اور بزعم خود جب بھی اپنے حقوق خطرہ میں دیکھیں یا امیر کا کوئی کام قابل اعتراض
سمجھیں تو شور کرتے ہوئے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں.چوتھے یہ کہ اگر واقعی امیر کا رویہ صریح
طور پر ناجائز اور قابل اعتراض ہو اور وہ اپنے اس رویہ میں نا قابل برداشت انتہا کو پہنچ جاوے اور اسے
اپنے ظالمانہ طریق پر اصرار ہو تو پھر اس کے متعلق کیا طریق اختیار کیا جاوے.ان چاروں اصولی مسائل
میں اسلام نے وہ تعلیم پیش کی ہے جو بہترین سیاست کی جان ہے اور اس میں بنی نوع انسان کی بہبودی اور
دنیا کے امن وامان کے لئے ایک ایسی بنیاد قائم کر دی گئی ہے جس پر قائم رہتے ہوئے اول تو حاکم و محکوم
کے تعلقات بگڑ ہی نہیں سکتے اور کبھی بگڑیں بھی تو ان کے خطرناک اور ضرررساں نتائج سے ملک محفوظ رہتا
ہے اور یہ تعلیم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی جبکہ دنیا میں بیشتر طور پر نسلی اور استبدادی حکومت کا
دور دورہ تھا اور اکثر ممالک نیابتی اور مشورہ کی حکومت کے خیال تک سے نا آشنا تھے.غیر
مسلموں کے ساتھ تعلقات اس نوٹ
کو ختم کرنے سے قبل اس
تعلیم کا ذکر کرنا بھی بے موقع
نہ ہوگا جو اسلام نے غیر مسلم حکومتوں یا اسلامی حکومت کے
اندر کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں دی ہے.سواس معاملہ میں اسلام سب سے
پہلے تو یہ اصول بیان کرتا ہے کہ عدل وانصاف کا معیار سب قوموں کے ساتھ ایک سا ہونا چاہئے اور
ایسا نہیں ہونا چاہئے اپنوں کے ساتھ تو عدل وانصاف کا معاملہ کیا جاوے اور جب دوسروں کا سوال ہو تو
اس اصول کو بھلا دیا جاوے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
یعنی ”اے مسلمانو! تم خدا کی خاطر دنیا میں نیکی اور عدل کے قائم کرنے کے لئے کھڑے
: سورۃ مائده : ۹
Page 747
۷۳۲
ہو جاؤ اور چاہئے کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں عدل و انصاف کے رستے سے نہ ہٹائے بلکہ تم سب
کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو.کیونکہ یہی طریق تقویٰ کا تقاضا ہے.پس تم متقی بنوا ور یا درکھو کہ
خدا تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے.“
یہ آیت غیر حکومتوں اور غیر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کے لئے بطور ایک بنیادی پتھر کے
ہے کیونکہ اس میں وہ اصل الاصول بتایا گیا ہے جس پر بین الا قوام اور بین الدول تعلقات قائم ہونے
چاہئیں اور غور کیا جائے تو یہ اصول ایسا زریں ہے کہ اگر فریقین کی طرف سے اس پر پورا پورا عمل ہو تو نہ
صرف یہ کہ بین الاقوام تعلقات کبھی بگڑ نہیں سکتے بلکہ وہ ایسی خوشگوار صورت میں قائم رہ سکتے ہیں کہ جس
میں بگڑنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو مگر افسوس کہ اکثر لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس اصول
کو عملا نظر انداز کر دیتے ہیں.اس جامع و مانع اصول کے بعد اسلام معاہدہ کے سوال کو لیتا ہے کیونکہ بین الاقوام تعلقات میں یہی
سوال سب سے زیادہ اہم ہے.چنانچہ فرماتا ہے: وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
یعنی ”اے مسلمانو! تم اپنے تمام عہدوں کو پورا کرو کیونکہ خدا کے حضور تمہیں اپنے عہدوں کے متعلق جواب دہ
ہونا پڑے گا.اس حکم کے ماتحت مسلمانوں کا یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاہدات کو نہایت
وفاداری اور دیانت کے ساتھ نبھائیں اور کسی ایسے فعل کے مرتکب نہ ہوں جو ان کے عہد و پیمان کی روح یا
الفاظ کے خلاف ہو.اسلام میں معاہدہ کی پابندی کا اس قدر تا کیدی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی مسلمان قوم
کا کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور پھر اس غیر مسلم قوم کے خلاف کوئی دوسری مسلمان قوم اس
مسلمان قوم کو اپنی مدد کے لئے بلائے تو اسے چاہئے کہ ہرگز اس کی مدد نہ کرے بلکہ بہر حال اپنے عہد پر
قائم رہے.چنانچہ فرماتا ہے:
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وكُمْ
فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ O :
یعنی ” جو لوگ مسلمان تو ہو گئے ہیں مگر وہ ہجرت کر کے اسلامی حکومت میں منسلک نہیں ہوئے ان کے
متعلق اے مسلما نو تم پر کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے ساتھ
ل : سورۃ بنی اسرائیل : ۳۵
: سورۃ انفال : ۷۳
Page 748
۷۳۳
ایک نہ ہو جائیں.ہاں اگر ایسے مسلمان تم سے کسی دینی معاملہ میں مدد مانگیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی
مدد کرو لیکن اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کے خلاف تم سے مدد مانگیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو
پھر تم ہر گز ان کی مدد نہ کرو اور بہر حال اپنے عہد پر قائم رہو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ
رہا ہے.کیا اس سے بڑھ کر ایفائے عہد اور عدل وانصاف کی کوئی تعلیم ہوگی ؟
اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ یعنی ” جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم کے قتل کا مرتکب
ہو گا جو کسی ( لفظی یا عملی ) معاہدہ کے نتیجہ میں اسلامی حکومت میں داخل ہو چکا ہے وہ (علاوہ اس دنیا کی
سزا کے ) قیامت میں جنت کی ہوا سے محروم رہے گا.پھر فرماتے ہیں:
مَنْ ظَلَمَ مَعَاهِدًا اَوِ نَتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسِهِ فَأَنَا
حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی جو مسلمان کسی ایسے غیر مسلم پر جس کے ساتھ اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے
کوئی ظلم کرے گا یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا یا اس پر کوئی ایسی ذمہ داری یا ایسا کام ڈالے گا جو اس کی
طاقت سے باہر ہے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی خوشی اور رضامندی کے لے گا تو اے مسلما نوسن لو کہ
میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے ہو کر اس مسلمان کے خلاف خدا سے انصاف چاہوں گا.“
مگر یا د رکھنا چاہئے کہ اسلام صرف منفی قسم کے سلوک تک اپنے آپ کو محمد و دنہیں رکھتا یعنی وہ
صرف یہ نہیں کہتا کہ کسی غیر مسلم کی حق تلفی نہ کرو اور بس بلکہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ نیکی اور احسان کا بھی
حکم دیتا ہے.چنا نچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا يَنْهُكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ :
یعنی ”اے مسلمانو ! خدا نے جو تمہیں ان ظالم کافروں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع فرمایا ہے جو
تمہارے دین کو مٹانے کے لئے تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان
غیر مسلموں کے ساتھ جو تمہارے دین کو جبر امٹانے کے درپے نہیں اور تم پر ظلم نہیں کرتے تعلق نہ رکھو
بلکہ تمہیں چاہئے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی اور عدل و احسان کا معاملہ کرو کیونکہ عدل واحسان
کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے.“
بخاری کتاب الجہاد : ابوداؤد بحوالہ مشکوۃ باب الصلح
: سورة ممتحنه : ۹
Page 749
۷۳۴
مذہبی آزادی اور دینی رواداری کے متعلق اسلامی تعلیم کا نمونہ جہاد کی بحث میں
مذہبی رواداری
گزر چکا ہے.قرآن شریف نے اپنی متعدد آیات میں اس بات پر خاص زور دیا ہے
کہ دین کا معاملہ ہر شخص کی ضمیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.پس دین میں قطعا کسی قسم کا جبر واکراہ نہیں ہونا
چاہئے.اور یہ تعلیم صرف کاغذوں کی زینت یا منبروں کی سجاوٹ نہیں تھی بلکہ اس پر نہایت دیانتداری کے
ساتھ عمل کیا جاتا تھا.چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا معاہدہ
جو اسلام میں کیا یعنی وہ معاہدہ جو ہجرت کے بعد مدینہ کی یہودی آبادی کے ساتھ کیا گیا اس کی بنیاد مذہبی
آزادی اور مذہبی آزادی کے اصول پر ہی قائم کی گئی تھی نے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بنو نضیر کو ان کی
غداری اور فتنہ انگیزی کی سزا میں مدینہ سے جلاوطن کیا گیا اور اس وقت انہوں نے اپنے ساتھ ان لوگوں
کو بھی لے جانا چاہا جو انصار کی اولاد تھے مگر انصار کے منت ماننے کے نتیجہ میں یہودی بنادئے گئے تھے تو
انصار نے انہیں مدینہ میں روک لینا چاہا لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اختلاف پیش
ہوا تو آپ نے یہ فرماتے ہوئے کہ دین کے معاملہ میں جبر نہیں ہوسکتا انصار کے خلاف فیصلہ فرمایا
اور بنو نضیر کو اجازت دی کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
میں ہی آگے چل کر یہ واقعات بھی ہمارے سامنے آئیں گے کہ جب خیبر کے یہودی اور نجران کے عیسائی
اسلامی حکومت میں داخل ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ اور عمل دونوں میں انہیں کامل آزادی
عطا کی ہے بلکہ روایت آتی ہے کہ جب نجران کے عیسائی مدینہ میں آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں مسجد نبوی کے اندر اپنے طریق پر عبادت کرنے کی اجازت عطا فرمائی اور جب بعض صحابہ نے انہیں
روکنا چاہا تو آپ نے ان صحابہ کومنع فرما دیا.چنانچہ ان عیسائیوں نے مشرق رو ہو کر عین مسجد نبوی میں اپنی
عبادت کے مراسم ادا کئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی خلفاء اربعہ نے مذہبی رواداری کا ایک کامل نمونہ
: سورة بقرة : ۲۵۷
سیرۃ ابن ہشام معاہدہ یہود بعد ہجرت
:
: ابو داؤد کتاب الجہاد
بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ خیبر وقصتہ اہل نجران وابو داؤد کتاب الخراج باب في اخذ الجزية وكتاب
الخراج ابو یوسف فصل قصة نجران وزرقانی جلد ۳ حالات غزوہ خیبر وجلد۴ حالات وفد نجران
ه: زرقانی جلد ۲ حالات وفد نجران
Page 750
۷۳۵
قائم کیا.چنانچہ حضرت ابوبکر کے متعلق روایت آتی ہے کہ وہ جب کبھی بھی کوئی اسلامی فوج روانہ فرماتے
تھے تو اس کے امیر کو خاص طور پر یہ ہدایت فرماتے تھے کہ غیر مسلم اقوام کی عبادت گاہوں اور ان کے
مذہبی بزرگوں کا پورا پورا احترام کیا جاوے یا اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب شام کا ملک فتح ہوا تو جو
معاہدہ وہاں کی عیسائی آبادی کے ساتھ مسلمانوں کا قرار پایا اس میں مذہبی آزادی اور مذہبی رواداری کی
روح سارے امور پر غالب تھی کے
جزیہ کا مسئلہ جزیہ کا مسئلہ بعض لوگوں کو قابل اعتراض نظر آتا ہے حالانکہ وہ محض ایک ٹیکس تھا جو
نظام حکومت کے چلانے کے لئے غیر مسلم رعایا سے لیا جاتا تھا اور جس کا فائدہ
بالواسطہ خود ٹیکس دینے والوں کو ہی پہنچتا تھا کیونکہ اس روپے سے حکومت ان کے حقوق کی حفاظت ان کے
آرام و آسائش اور ان کی بہبودی کا انتظام کرتی تھی اور ان کے جان ومال کی حفاظت کے لئے افواج
مہیا کرتی تھی اور اگر یہ اعتراض ہو کہ یہ ٹیکس غیر مسلم رعایا کے ساتھ مخصوص کیوں تھا تو اس کا جواب یہ
ہے کہ اول تو یہ ٹیکس فوجی خدمت کا معاوضہ سمجھا جاتا تھا جو مسلمان سپاہی سرانجام دیتے تھے مگر جس سے
غیر مسلم رعایا آزاد رکھی گئی تھی یعنی جہاں ہر مسلمان گویا جبری بھرتی کے قانون کے ماتحت تھا وہاں غیر مسلم
رعایا اس پابندی سے آزاد تھی.اس صورت میں یہ انصاف کا تقاضا تھا کہ اسلامی حکومت کے فوجی
اخراجات کا بوجھ ایک حد تک غیر مسلم رعایا پر بھی ڈالا جاتا اور یہی جزیہ تھا.علاوہ از میں غور کرنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اسلام میں ٹیکس کے معاملہ کو تین شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے:
اول وہ ٹیکس جو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص تھے مثلا زکوۃ.دوم وہ ٹیکس جو صرف غیر مسلموں
کے ساتھ خاص تھے مثلاً جزیہ.سوم مشترک ٹیکس جو حسب حالات سب پر لگائے جاسکتے تھے مثلاً زمین
کا مالیہ.اس تقسیم و تفریق کی وجہ یہ تھی کہ اسلامی حکومت کو بعض ایسے کام بھی کرنے پڑتے تھے جو مسلمانوں
کے دینی مصالح کے ساتھ خاص تھے اور یہ انصاف سے بعید تھا کہ ان کا بوجھ غیر مسلم رعایا پر ڈالا جاتا
لہذا کمال دیانت داری کے ساتھ اسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بعض ٹیکس جدا جدا کر دئے.چنانچہ جہاں مسلمانوں کے مخصوص ٹیکس یعنی زکوۃ میں دینی اور سیاسی اغراض ہر دو مخلوط طور پر شامل کر دی
مؤطا امام مالک کتاب الجہاد
دیکھو تاریخ طبری.ابن جریر و تاریخ کامل ابن اثیر وفتوح البلدان بلاذری و کتاب الخراج ابو یوسف وفتوح الشام
واقدی حالات فتح شام
Page 751
۷۳۶
گئیں وہاں غیر مسلموں کے مخصوص ٹیکس یعنی جزیہ کے مصارف میں کوئی دینی غرض شامل نہیں کی گئی بلکہ
اسے عام رکھا گیا ہے.یہی وجہ ہے کہ بیشتر صورتوں میں زکوۃ کا ٹیکس جو مسلمانوں کے لئے خاص ہے
جزیہ کے ٹیکس سے بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس کے مصارف زیادہ ہیں.پس غور کیا جاوے تو جزیہ کے ٹیکس
کا غیر مسلموں کے ساتھ مخصوص کر دیا جانا اسلام اور بانی اسلام کی اعلیٰ درجہ کی دیانت کا ثبوت ہے مگر
افسوس ہے کہ نادان لوگوں نے اسی کو ایک اعتراض کی بنیاد بنالیا ہے.اب رہا جزیہ کی تشخیص و تحصیل کا سوال.سو اس معاملہ میں بھی اسلام نے ایک ایسا اعلیٰ نمونہ قائم کیا ہے
جس کی نظیر کسی دوسری جگہ نہیں ملتی.اس کے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ جاننی چاہئے کہ اسلام نے جزیہ
کے ٹیکس کی کوئی شرح معین نہیں کی بلکہ اسے ہر زمانہ اور ہر قوم کے حالات پر چھوڑ دیا ہے چنانچہ تاریخ سے
ثابت ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل کے ساتھ جزیہ کے متعلق مختلف
صورتیں اور مختلف شرحیں اختیار کی تھیں.چنانچہ مثلاً نجران کے عیسائیوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجموعی طور پر دو ہزار چادر میں اور بعض ضروری چیزیں سالانہ مقرر کی تھیں سے مگر اس کے مقابل پر یمن کے
لوگوں سے اوسطاً ایک دینار فی کس سالا نہ مقرر ہوا تھا.اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
آپ کے خلفاء نے بھی یہی طریق جاری رکھا کہ ہر قوم کے مناسب حال ان سے جزیہ کا ٹیکس وصول کیا جاتا
تھا اور افراد پر اس ٹیکس کی تقسیم ایسے رنگ میں کی جاتی تھی کہ ہر شخص پر اس کی مالی طاقت کے مطابق بوجھ
پڑتا تھا.چنانچہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ خلفاء اربعہ کے زمانہ میں جزیہ کے ٹیکس کی صورت عموماً یہ تھی کہ
خوشحال لوگوں سے اڑتالیس درہم سالا نہ لیا جاتا تھا.اور متوسط الحال لوگوں سے چوہیں درہم سالانہ اور
ان سے
کم حیثیت لوگوں سے صرف بارہ درہم سالا نہ لیا جا تا تھا.یہ خفیف ٹیکس بھی ساری غیر مسلم آبادی پر نہیں لگایا جا تا تھا بلکہ مندرجہ ذیل اقسام کے لوگ اس
ل : سورۃ توبہ : اے
: سورۃ توبه
۲۹ :
سے بخاری بحوالہ فتح الباری جلد ۸ صفحه ۷۳ وابو داؤ د کتاب الخراج باب فــي اخــذ الـجـزيـة وكتاب الخراج
قاضی ابو یوسف
عرب کا ایک معمولی سونے کا سکہ تھا
ه ابوداؤ د کتاب الخراج باب فى اخذ الجزية
عرب کا ایک معمولی چاندی کا سکہ تھا
کتاب الخراج قاضی ابو یوسف فصل فِي مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ
Page 752
۷۳۷
سے مستثنیٰ تھے.-1
-r
تمام وہ لوگ جو مذہب کے لئے اپنی زندگی وقف رکھتے تھے.تمام عورتیں اور بچے.تمام بوڑھے اور معمر لوگ جو کام کے ناقابل تھے.۴.تمام نابینا لوگ اور اسی قسم کے دوسرے معذور لوگ جو کوئی کام نہ کر سکتے تھے.۵.تمام مساکین اور غرباء جن کی مالی حالت جزیہ کی ادائیگی کے قابل نہ تھی.ہے
جزیہ کی تحصیل میں یہ اصول مدنظر رکھے جاتے تھے.(الف) جزیہ دینے والے کو اختیار تھا کہ خواہ نقد ادا کرے یا اس کی قیمت کے اندازے پر کوئی
چیز دے دے.( ب ) جزیہ کی وصولی کے متعلق تاکیدی حکم تھا کہ اس معاملہ میں کسی قسم کی سختی سے کام نہ لیا جاوے
اور بالخصوص بدنی سزا سے منع کیا گیا تھا.( ج ) اگر کوئی شخص ایسی حالت میں مرجاتا تھا کہ اس کے ذمہ جزیہ کی کوئی رقم واجب الادا ہوتی تھی
تو وہ معاف کر دی جاتی تھی اور مرنے والے کے ورثاء اور ترکہ کو اس کا ذمہ وار نہیں قرار دیا جاتا تھا.ہے
کیا یہ مراعات آج کوئی قوم کسی دوسری قوم سے کرتی ہے؟ پھر یہی نہیں کہ جزیہ کی تشخیص میں
نرمی سے کام لیا جاتا تھا بلکہ اگر جزیہ واجب ہو جانے کے بعد بھی کسی شخص کی مالی حالت جزیہ ادا کرنے
کے قابل نہ رہتی تھی تو اسے جزیہ کی رقم معاف کر دی جاتی تھی.چنانچہ ذیل کا تاریخی واقعہ اس کی ایک
دلچسپ مثال ہے.روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں بعض
غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرنے میں کچھ سختی کی جارہی تھی.یہ دیکھ کر حضرت عمر فور ارک گئے اور غصہ کی
حالت میں دریافت فرمایا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ” یہ لوگ جزیہ ادا نہیں کرتے اور کہتے
ہیں کہ ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے.حضرت عمرؓ نے فرمایا تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ان پر وہ بوجھ ڈالا
”
جاوے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے.انہیں چھوڑ دو.میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ
جو شخص دنیا میں لوگوں
کو تکلیف دیتا ہے وہ قیامت کے دن خدا کے عذاب کے نیچے ہو گا.چنانچہ ان لوگوں
کا جزیہ معاف کر دیا گیا.، ۲، ۳: کتاب الخراج فصل فِي مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ
Page 753
۷۳۸
حضرت عمرؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی ارشادات کے ماتحت اپنی غیر مسلم رعایا
کا اس قدر خیال تھا کہ انہوں نے فوت ہوتے ہوئے خاص طور پر ایک وصیت کی جس کے الفاظ
یہ تھے : ” میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اسلامی حکومت کی غیر
مسلم
رعایا سے بہت نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے.ان کے معاہدات کو پورا کرے.ان کی حفاظت
کرے.ان کے لئے ان کے دشمنوں سے لڑے اور ان پر قطعاً کوئی ایسا بوجھ یا ذمہ داری نہ ڈالے
جو ان کی طاقت سے زیادہ ہولے
عام سلوک اور سیاسی تعلقات عام سلوک اور سیاسی تعلقات کے معاملہ میں بھی اسلام نے ایسا
نمونہ قائم کیا جس کی مثال کسی دوسری قوم میں نہیں ملتی.خیبر کے
یہودیوں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کا ذکر اوپر گزر چکا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ان سے محاصل کی بٹائی کے لئے اپنے صحابی عبد اللہ بن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے.آپ کی تعلیم کے ماتحت
عبداللہ بن رواحہ فصل کی بٹائی میں اس قدر نرمی سے کام لیتے تھے کہ فصل کے دو حصے کر کے یہودیوں
کو اختیار دے دیتے تھے کہ اب ان حصوں میں سے جو حصہ بھی تم پسند کرو لے لو اور پھر جو حصہ پیچھے رہ جاتا
تھا وہ خود لے لیتے تھے.حضرت عمر کے زمانہ میں جب شام فتح ہوا تو معاہدہ کی رو سے مسلمانوں نے شام
کی عیسائی آبادی سے ٹیکس وغیرہ وصول کیا.لیکن اس کے تھوڑے عرصہ بعد رومی سلطنت کی طرف سے پھر
جنگ کا اندیشہ پیدا ہو گیا جس پر شام کے اسلامی امیر حضرت ابوعبیدہ نے تمام وصول شدہ ٹیکس عیسائی آبادی
کو واپس کر دیا اور کہا کہ جب جنگ کی وجہ سے ہم تمہارے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو ہمارے لئے جائز نہیں
کہ یہ ٹیکس اپنے پاس رکھیں.عیسائیوں نے یہ دیکھ کر بے اختیار مسلمانوں کو دعا دی اور کہا ” خدا کرے تم
رومیوں پر فتح پاؤ اور پھر اس ملک کے حاکم بنو.چنانچہ جب مسلمانوں نے دوبارہ فتح حاصل کی تو علاقہ کی
عیسائی آبادی نے بڑی خوشی منائی اور واپس شدہ ٹیکس پھر مسلمانوں کو ادا کئے.تے یہ اسی قسم کے حسن سلوک کا
نتیجہ تھا کہ جب حضرت عمر خلیفہ ثانی شام میں تشریف لے گئے تو وہاں کے عیسائی لوگ گاتے اور بجاتے
ہوئے ان کے استقبال کے لئے نکلے اور ان پر تلواروں کا سایہ کیا اور پھولوں کی بارش برسائی ہے
کتاب الخراج صفحه ۷۲
في الخرص نیز دیکھو مؤطا مالک کتاب المساقاة
فتوح البلدان بلاذری صفحه ۱۴۶
: ابو داؤد کتاب البیوع باب فِي الْمُسَاقَاة وباب
کتاب الخراج ابو یوسف صفحه ۸۰ ۸۲٬۸۱
Page 754
۷۳۹
ملکی عہدوں کے معاملہ میں بھی غیر مسلم رعایا کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا.چنانچہ حضرت عمرؓ نے
ایک عیسائی ابو زبید نامی کو ایک جگہ کا عامل مقر ر فر مایا تھا لے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تعامل کے ماتحت حضرت عمر کو اسلامی حکومت کی غیر مسلم
رعایا کے حقوق اور ان کے آرام و آسائش کا اتنا خیال رہتا تھا کہ وہ اپنے گورنروں کو تاکید کرتے رہتے
تھے کہ ذمیوں کا خاص خیال رکھیں اور خود بھی ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں
ہے.چنانچہ ایک دفعہ ذمیوں کا ایک وفد حضرت عمر کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت عمر نے ان سے
پہلا سوال یہی کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا
مَا نَعْلَمُ إِلَّا وَفَاء وَحُسُنَ مَلِكَةٍ _ یعنی ”ہم نے مسلمانوں کی طرف سے حسن وفا اور حسن سلوک کے
سوا کچھ نہیں دیکھا.“
عدل و انصاف محکمہ قضا و عدالت میں مسلم اور غیر مسلم رعایا کے حقوق قانونی رنگ میں تو مساوی تھے
ہی مگر عملاً بھی انصاف کا ترازو کسی طرف جھکنے نہیں پاتا تھا.چنانچہ ہم دیکھ چکے
ہیں کہ جب بنو نضیر کی جلاوطنی کے موقع پر انصار اور یہود کے درمیان اختلاف پیدا ہوا یعنی یہودی لوگ
انصار کی اولاد کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے اور انصار انہیں روکتے تھے تو اس پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاف اور یہود کے حق میں فیصلہ فرمایا تے اسی طرح روایت آتی ہے کہ جب
ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے سامنے ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ حق یہودی
کے ساتھ ہے مسلمان کا مقدمہ خارج کر کے یہودی کے حق میں ڈگری دی.انہی کے زمانہ میں ایک دفعہ
ایک یہودی قتل ہو گیا اور اس کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں چلتا تھا.حضرت عمرؓ کو اس کا علم ہوا تو وہ گھبرا کر
گھر سے نکل آئے اور صحا بہ کو مسجد میں جمع کر کے منبر پر چڑھ گئے اور ایک نہایت زور دار خطبہ دیا جس میں کہا
کہ خدا نے مجھے خلیفہ بنایا اور حکومت اسلامی کی باگ ڈور میرے ہاتھ میں دی.اب کیا میرے ہوتے
ہوئے مخلوق خدا کا اس طرح خون ہو گا.تم لوگوں کو خدا کی قسم ہے کہ جسے اس واقعہ کے متعلق کچھ علم
ہو وہ مجھے بتائے اس پر ایک صحابی بکر بن شداخ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا.یا امیر المومنین! یہ قتل مجھ سے
اصابہ جلد ۹ صفحه ۱۴۷ حالات ابوز بیدا لطائی الشاعر
ابوداؤد کتاب الجہاد باب فى الاسير يكره على الاسلام
موطا امام مالک کتاب الاقضية باب الترغيب في القضاء بالحق
۲ : طبری جلد ۵ صفحه ۲۵۶۰
Page 755
۷۴۰
سرزد ہوا ہے.حضرت عمر نے جواب دیا.اللہ اکبر ! تم اس کے قاتل ہو! تم سے قصاص لیا جائے گا ورنہ
کوئی بریت ہے تو پیش کرو.غریب ذمیوں کی امداد اسلامی حکومت میں غریب اور نادار غیر مسلم رعایا کی مالی امداد کا بھی انتظام
کیا جاتا تھا.چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک بوڑھے یہودی کو بھیک
مانگتے دیکھا تو اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا.بوڑھا ہو گیا ہوں اور نظر کمزور ہے.کام ہونہیں
سکتا اور جزیہ کی رقم بھی ابھی مجھ پر لگی ہوئی ہے.یہ سن کر حضرت عمرؓ بے چین ہو گئے.فوراً اسے اپنے
ساتھ لیا اور اپنے گھر لا کر مناسب امداد دی اور پھر بیت المال کے افسر کو بلا کر کہا کہ یہ کیا بے انصافی ہے
کہ ایسے لوگوں پر جزیہ لگایا جاتا ہے! ہمیں تو حکم ہے کہ غرباء کی امداد کریں نہ کہ الٹا ان پر ٹیکس
لگائیں.اس کے بعد ایک عام حکم جاری فرمایا کہ ایسے لوگوں پر جزیہ نہ لگایا جاوے بلکہ اس قسم کے مستحق
لوگوں کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاوے کے ذمیوں کی امداد تو الگ رہی اسلام میں حربی دشمنوں کی
امداد کی مثالیں بھی مفقود نہیں ہیں چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ۵ ہجری میں مکہ میں قحط پڑا تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے مکہ والوں کی امداد کے لئے کچھ چاندی بھجوائی حالانکہ
ابھی تک قریش مکہ اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے.احساسات کا احترام
جذبات واحساسات کا رشتہ نہایت نازک ہوتا ہے اور فاتح اور غالب اقوام
عموماً اس معاملہ میں بہت بے اعتنائی دکھاتی ہیں کیونکہ اس کا دار و مدار کسی
قانون پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اس روح پر ہوتا ہے جو قلوب میں مخفی ہوتی ہے اور جس پر کوئی مادی قانون
حکومت نہیں کر سکتا.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے غلبہ اور حکومت کے زمانہ میں بھی
غیر مسلموں کے احساسات کا بہت خیال رکھتے تھے.چنانچہ ایک دفعہ مدینہ میں ایک یہودی نو جوان بیمار
ہو گیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے.اور اس کی
حالت کو نازک پا کر آپ نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی.وہ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوا مگر چونکہ اس کا باپ
زندہ تھا اور اس وقت پاس ہی کھڑا تھا.وہ ایک سوالی کی ہیئت بنا کر باپ کی طرف دیکھنے لگ گیا.باپ نے
لے : اسدالغابہ ذکر بکر بن شداخ نیز اس غلط خیال کی تردید کے لئے کہ ایک مسلمان کا فر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاسکتا
دیکھو طحاوی باب المومن يقتل الكافر متعمداً کتاب الخراج قاضی ابو يوسف فصل في من تجب
۳ : تاریخ الخمیس جلد اصفحه ۵۲۸
عليه الجزية صفحه ۷۴
Page 756
۷۴۱
،،
کہا ” بیٹے ! (اگر تمہیں تسلی ہے تو بے شک ) ابوالقاسم کی بات مان لو.لڑکے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان
ہو گیا.جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا ”خدا کا شکر ہے کہ ایک روح آگ کے
عذاب سے نجات پاگئی..جب شام کا ملک فتح ہوا اور وہاں کی عیسائی آبادی اسلامی حکومت کے ماتحت آگئی تو ایک دن جبکہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ کے شہر میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے
تھے ان کے پاس سے ایک عیسائی کا جنازہ گزرا.یہ دونوں اصحاب اسے دیکھ کر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے.ایک مسلمان نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ نہیں تھا اور ان اخلاق سے نا آشنا تھا جو
اسلام سکھاتا ہے یہ دیکھ کر بہت تعجب کیا اور حیران ہو کر سہل اور قیس سے کہا کہ یہ تو ایک ذمی کا جنازہ
ہے.انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! ہم جانتے ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ آپ
غیر مسلموں کے جنازہ کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کیا ان میں خدا کی پیدا کی
ہوئی جان نہیں ہے؟.دوسری اقوام کے مذہبی بزرگوں
کا احترام بین الاقوام مناقشات کی تہ میں بیشتر طور پر یہ
جذ بہ کام کرتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے
مذہبی پیشواؤں کا احترام نہیں کرتی اور اپنے بزرگوں کے سوا باقی سب کو جھوٹا اور مفتری اور مفسد فی الارض
قرار دیتی ہے اس معاملہ میں اسلام یہ تعلیم پیش کرتا ہے کہ خدا کسی ایک قوم یا ایک ملک کا خدا نہیں ہے
بلکہ وہ ساری دنیا کا خدا ہے پس جس طرح اس نے دنیا کی جسمانی زندگی کے لئے ایسے سامان پیدا کئے
ہیں جو کسی ایک قوم کے ساتھ خاص نہیں.اسی طرح اس کی ازلی رحمت نے دنیا کی روحانی زندگی کے لئے
بھی سب کے ساتھ مساویانہ سلوک کیا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا اَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ
هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّللَهُ ، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيرٌ یعنی
ہم نے ہر قوم میں اپنا رسول بھیج کر لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ صرف خدا کی پرستش کرو اور شیطانی
رستوں کے قریب نہ جاؤ لیکن افسوس کہ صرف بعض نے ہماری نصیحت کو مانا اور بعض نے گمراہی کا رستہ
: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی.۲: بخاری ابواب الجنائز باب اذا اسلم الصبی
بخاری ابواب الجنائز باب مَنْ قَامَ لِجَنَازَةِ يَهُودِي ۴ : سورة پحل: ۳۷ ۵: سورة فاطر: ۲۵
Page 757
۷۴۲
اختیار کر لیا مگر ہم نے اپنی طرف سے سب کے ساتھ ایک سا سلوک کیا کیونکہ دنیا کی ایک قوم بھی ایسی نہیں
جس کی طرف ہم نے کوئی نصیحت کرنے والا بھیج کر اس کے لئے ہدایت کا سامان نہ پیدا کیا ہو.اس آیت
کریمہ کے ماتحت ایک مسلمان کے لئے دنیا کی ہر قوم کا مذہبی بانی ایک مقدس ہستی بن جاتا ہے اور وہ اس
بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہر قوم کے مذہبی پیشوا کو خدا کے ایک نبی اور رسول کی حیثیت میں قبول کرے.اس کے لئے ہندوؤں کے کرشن ، بدھ مذہب والوں کے گوتم بدھ، چینیوں کے کنٹوشس، پارسیوں کے
زرتشت، یہودیوں کے موسیٰ اور عیسائیوں کے مسیح علیہم السلام سب ایک ہی واحد آسمانی خدا کے مقدس
پیغامبر ہیں جن کے ذریعہ سے دنیا نے اپنے اپنے وقت میں ہدایت کا نور پایا.اس مبارک تعلیم کے ماتحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری اقوام کے مذہبی پیشواؤں کی عزت کا
اس قدر خیال تھا کہ ایک دفعہ جب ایک صحابی نے کسی یہودی کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت
موسیٰ پر ایسے رنگ میں فضیلت بیان کی جس سے اس یہودی کے دل کو صدمہ پہنچا تو آپ نے اس صحابی کو
علامت فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا یہ کام نہیں کہ خدا کے نبیوں میں اس طرح بعض کو بعض سے افضل بیان کرتے
پھرو اور پھر آپ نے حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت بیان کر کے اس یہودی کی دلداری فرمائی یا ایک
دوسرے موقع پر جبکہ آپ طائف سے مکہ کو واپس آرہے تھے آپ کو ایک عد اس نامی شخص ملا جس نے آپ
سے ذکر کیا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں.آپ نے بے ساختہ فرمایا ”نینوا ! یونس بن متی کا شہر ! یونس میرے
بھائی تھے.میں اسی خدا کا رسول ہوں جس نے یونس کو مبعوث کیا تھا.“ یہ ذہنیت کیسی مبارک ،کیسی دلکش
اور اخوت اور امن کے جذبات سے کیسی معمور ہے !مگر افسوس کہ دنیا نے اس کی قدر نہیں کی.یہ اس ضابطہ اخلاق کا مختصر نقشہ ہے جو غیر قوموں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے متعلق مقدس بانی اسلام
نے پیش کیا اور جس پر آپ کے صحابہ اور آپ کے خلفاء نے عملاً کار بند ہوکر یہ بتادیا کہ یہ تعلیم صرف
کاغذوں کی زینت یا منبروں کی سجاوٹ نہیں بلکہ سیاست اسلامی کا ایک ضروری اور عملی حصہ ہے جس کے
بغیر کوئی حکومت جو اسلام کی طرف منسوب ہوتی ہے صحیح معنوں میں اسلامی حکومت نہیں کہلا سکتی.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمُ
اس جگہ سیرۃ خاتم النبیین کا حصہ دوم ختم ہوا )
ل : بخاری کتاب بدء الخلق باب قول الله تعالٰى وَإِنَّ يُوْنَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
: سیرۃ ابن ہشام جلد اصفحہ ۱۴۷
Page 759
3
صلی اللہ علیہ وسلم
سیرت خاتم النبین
Page 760
۷۴۵
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
عرض حال
سيرة خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ سوم کا پہلا جز و ہدیہ ناظرین کرتے ہوئے میری طبیعت
میں اس وجہ سے کافی تامل ہے کہ یہ حصہ اس احتیاط کے ساتھ نہیں لکھا گیا جس احتیاط سے کہ سابقہ حصے لکھے
گئے تھے اور اس کا آخری حصہ تو گویا بالکل قلم برداشتہ ہی لکھا گیا اور یہ انداز ایک تاریخی تحقیق کے لئے یقیناً
مناسب نہیں.اسی طرح اس حصہ کی نظر ثانی بھی ایسے حالات میں ہوئی ہے کہ میں اس کے متعلق کسی طرح
تسلی کا اظہار نہیں کر سکتا.قادیان سے باہر آنے کے بعد کتابوں کا بہت سا ذخیرہ تو قادیان میں ہی رہ گیا اور
جو حصہ پاکستان میں پہنچا وہ لاہور اور چنیوٹ اور ربوہ احمد نگر وغیرہ میں منتشر پڑا ہے اس لئے حوالوں کی
آخری چھان بین بلکہ بعض صورتوں میں تو ابتدائی چھان بین بھی تسلی بخش صورت میں نہیں ہوسکتی اور مجھے
اکثر جگہ حوالہ در حوالہ پر اکتفا کرنی پڑی ہے.مثلاً اگر زرقانی نے یہ لکھا ہے کہ ابن سعد نے فلاں بات یوں
بیان کی ہے تو میں اسے موجودہ تصنیف میں قبول کر لیتا ہوں حالانکہ اس سے پہلے اصل ماخذ کی طرف
رجوع کر کے ذاتی پڑتال کے بعد اندراج کیا کرتا تھا.اس کے علاوہ آخری حصہ لاہور میں آکر بہت جلدی
میں لکھنا پڑا ہے اس لئے دلجمعی کی نظر ثانی کے نتیجہ میں جو اصلاح اور تصحیح ممکن ہوسکتی ہے وہ اسے میسر نہیں آئی
مگر بہر حال جو کچھ بھی موجودہ حالات کی مجبوریوں کے ماتحت لکھا جاسکا ہے وہ دوستوں کے اس مشورہ کے
نتیجہ میں کہ موجودہ مواد بہر حال شائع ہو جانا چاہئے ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے.اگر خدا نے توفیق دی تو
انشاء اللہ طبع ثانی کے وقت ضروری اصلاح کی جاسکے گی.جیسا کہ میں الفضل میں اعلان کر چکا ہوں یہ حصہ مکمل نہیں ہے بلک صرف غزوہ بنو قریظہ کے بعد کے
حالات سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خطوط کے زمانہ تک محدود ہے اسی لئے میں نے اس
کا نام ” سيرة خاتم النبیین حصہ سوم جز واول رکھا ہے.جب بقیہ جز وشائع ہوگی تو انشاء اللہ حصہ سوم مکمل
Page 761
۷۴۶
ہو جائے گا.اس حصہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (فدا نفسی ) کے اس خط کا بلاک فوٹو بھی درج کیا جارہا
ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس کو لکھا تھا.اگر چہ ان ساڑھے تیرہ سوسال کے
عرصہ میں عربی کے رسم الخط میں کافی تبدیلی آچکی ہے لیکن غور کرنے سے بیشتر الفاظ پڑھے جاسکتے ہیں اور
یہ الفاظ بعینہ وہی ہیں جو اسلامی روایتوں سے اس خط کے ثابت ہوتے ہیں.پس میں نے نہ صرف تبرک
کے خیال سے بلکہ اس خیال سے بھی کہ اس خط کی دریافت احادیث اور تاریخ اسلام کی صحت کا ایک زندہ
ثبوت ہے اس خط کا فوٹو کتاب میں درج کر دیا ہے اور میرا دل اس نقشہ کو تصور میں لا کر خاص روحانی سرور
حاصل کرتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منتخب صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ مبارک الفاظ املا
فرمارہے ہوں گے اور صحابہ کے دل اس مقدس انتظار کی کیفیت سے معمور ہوں گے کہ دیکھئے ان روحانی
آبشاروں کے چھینٹوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.دوست دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کتاب کے بقیہ حصہ یا حصوں کی تکمیل کی بھی توفیق عطا کرے اور
اسے دنیا کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے.وبالله التوفيق وهو المستعان
خاکسار
مرزا بشیر احمد آف قادیان
حال رتن باغ.لاہور
۲ / اپریل ۱۹۴۹ء
Page 762
۷۴۷
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
مدنی زندگی کے دوسرے دور کا آغاز
صلح حدیبیہ سے پہلے کا زمانہ
جیسا کہ اس کتاب کے حصہ دوم کے آخر میں بیان کیا جا چکا ہے ۶ ہجری کی ابتدا سے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے.اس نئے دور کی نمایاں خصوصیات تین تھیں:
اول.یہ کہ اب مدینہ کا شہر غیر مسلم عصر سے عملاً پاک ہو چکا تھا اور گومنافقین کا گروہ اب تک
مدینہ میں موجود تھا اور یہ لوگ اپنی قلبی عداوت اور مخفی چالبازیوں میں اس وقت غالبا آگے سے بھی زیادہ
جوش و خروش میں تھے مگر بہر حال وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور جہاں تک ظاہری نظام کا تعلق ہے
وہ اسلامی سوسائٹی کا حصہ تھے.دوم.گو قریش مکہ ابھی تک اسلام کے خلاف میدان عمل میں تھے مگر غزوہ احزاب کی ناکامی سے
انہیں ایسا دھکا لگ چکا تھا کہ اب وہ اسلام کی عداوت کا مرکزی نقطہ نہیں رہے تھے.سوم.میدان کارزاراب مدینہ سے ہٹ کر عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گیا تھا.اس مؤخر الذکر
تبدیلی کی وجہ سے مسلمانوں کی بیرونی مہمیں بھی لازما زیادہ کثرت اور زیادہ تنوع اختیار کر گئی تھیں اور
ان کا حلقہ آگے سے بہت زیادہ وسیع ہو کر گونا گوں معرکوں کا منظر پیش کرنے لگا تھا.چنانچہ تاریخ سے پتہ
لگتا ہے کہ ہجرت کا چھٹا سال جس میں ہم اب داخل ہو رہے ہیں مسلمانوں کے لئے غیر معمولی نقل و حرکت
کا سال تھا جس میں انہیں کم و بیش اٹھارہ مرتبہ مدینہ سے نکلنا پڑا اور ان مہمات میں سے ایک مہم
( یعنی غزوہ حدیبیہ ) تو خاص طور پر نہایت اہم اور نہایت وسیع الاثر تھی.میور ایڈیشن ۱۹۲۳ء صفحه ۳۴۱
Page 763
۷۴۸
دراصل گوعرب کے قبائل غزوہ احزاب میں جو اواخر ۵ ہجری میں ہوا اپنا انتہائی زور لگا دینے کے بعد
اس خیال سے تو عملاً مایوس ہو چکے تھے کہ مدینہ پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو ان کے گھر میں ہی ملیا میٹ کیا
جاسکتا ہے مگر ابھی تک عداوت اسلام کی آگ ان کے سینوں میں اسی طرح شعلہ زن تھی بلکہ غزوہ احزاب
کی ذلت بھری ناکامی نے ان کی دلی عداوت کو اور بھی بھڑ کا دیا تھا.اس لئے اب اگر ایک طرف عرب کے
وحشی اور خونخوار قبائل نے مدینہ پر باقاعدہ حملہ کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی وہ پیشگوئی پوری ہوگئی تھی کہ غزوہ احزاب کے بعد یہ لوگ مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوں گے تو دوسری طرف
وہ اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لئے نئے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر میدان میں نکل
رہے تھے.چنانچہ اس زمانہ میں انہوں نے تین تدابیر اختیار کیں.اول انہوں نے یہ تجویز کی کہ مدینہ سے باہر جن جن قبائل میں اسلام کا اثر پہنچ رہا تھا یا جن میں اثر
پہنچنے کا احتمال تھا وہاں اسلام کی اشاعت کو جبر آروک دیا جاوے تا کہ کوئی نیا شخص مسلمان ہو کر اور مدینہ کی
طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی تقویت کا باعث نہ بنے.دوسرے یہ کہ مدینہ کے مضافات پر خفیہ خفیہ چھاپے مار کر مسلمانوں کے جان و مال کو نقصان
پہنچایا جاوے.تیسرے یہ کہ کسی مخفی تدبیر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام اسلام کا مرکزی نقطہ تھے قتل
کروا دیا جاوے.ہر چند کہ یہ تینوں تجاویز ایک حد تک پہلے سے کفار کے مد نظر تھیں اور وہ عملاً ان کے لئے کوشاں بھی
رہتے تھے مگر اب انہوں نے دوسری طرف سے خیال ہٹا کر گویا اپنا سارا زور انہی تجاویز کے کامیاب
بنانے میں صرف کرنا شروع کر دیا.چنانچہ وہ مہمات جن کا ذکر اب شروع ہوتا ہے ان کا باعث زیادہ تر
کفار عرب کی یہی تدابیر تھیں.ہم ان میں سے خاص خاص غزوات وسرایا کا ذکر کسی قدر تفصیلا اور باقی
کا مجملاًہد یہ ناظرین کرتے ہیں.ابھی ۶ ھ شروع ہی ہوا تھا اور قمری سال سریہ قرطا.محرم ۶ ہجری مطابق مئی، جون ۶۲۷ ء
کے پہلے مہینہ یعنی محرم کی ابتدائی تاریخیں
ل : تاریخ میں ان تجاویز کا اس رنگ میں صراحت سے ذکر نہیں آتا لیکن بعد کے واقعات سے ان کے متعلق یقینی استدلال
ہوتا ہے.
Page 764
۷۴۹
تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل نجد کی طرف سے خطرہ کی اطلاعات پہنچیں.یہ اندیشہ قبیلہ قرطا کی
طرف سے تھا جو قبیلہ بنو بکر کی ایک شاخ تھا اور نجد کے علاقہ میں بمقام ضریہ آباد تھا جو مدینہ سے سات یوم
کی مسافت پر واقع تھا.یہ خبر پاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا تمہیں سواروں کا ایک ہلکا سا دستہ
اپنے ایک صحابی محمد بن مسلمہ انصاری کی کمان میں نجد کی طرف روانہ فرما دیا مگر اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں
میں کچھ ایسا رعب پیدا کر دیا کہ وہ معمولی سے مقابلہ کے بعد ہی بھاگ نکلے اور گو اس زمانہ کے طریق جنگ
کے مطابق مسلمانوں کے لئے یہ موقع تھا کہ وہ دشمن کی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیتے کیونکہ دشمن انہیں
چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا مگر محمد بن مسلمہ نے عورتوں اور بچوں سے کوئی تعرض نہیں کیا اور عام سامان غنیمت
لے کر جو اونٹوں اور بکریوں پر مشتمل تھا مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے.ہے
ثمامہ بن اثال رئیس بیمامہ کا اسلام لا نا محرم ۶ ہجری اس مہم کی واپسی پر شمامہ بن انغال کے
قید کئے جانے کا واقعہ پیش آیا.یہ شخص
یامہ کا رہنے والا تھا اور قبیلہ بنوحنیفہ کا ایک بہت با اثر رئیس تھا اور اسلام کی عداوت میں اس قدر بڑھا ہوا تھا
کہ ہمیشہ بے گناہ مسلمانوں کے قتل کے درپے رہتا تھا.چنانچہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک
اینچی اس کے علاقہ میں گیا تو اس نے تمام قوانین جنگ کو بالائے طاق رکھ کر اس کے قتل کی سازش کی.بلکہ ایک دفعہ اس نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی ارادہ کیا تھا.جب محمد بن مسلمہ کی
پارٹی شمامہ کو قید کر کے لائی تو انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے بلکہ انہوں نے اسے محض شبہ کی بنا پر
قید کر لیا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ ثمامہ نے بھی کمال ہوشیاری کے ساتھ ان پر اپنی حقیقت ظاہر نہیں ہونے دی
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسلام کے خلاف خطرناک جرائم کا مرتکب ہو چکا ہوں اور اگر اسلام کے ان
غیرت مند سپاہیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں تو وہ شاید مجھ پر سختی کریں یا قتل ہی کر دیں مگر خود
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہتر سلوک کی توقع رکھتا تھا.چنانچہ مدینہ کی واپسی تک محمد بن مسلمہ کی
پارٹی پر مامہ کی شخصیت مخفی رہی.ے اس زمانے کے طریق سفر کے لحاظ سے یہ فاصلہ قریباً ڈیڑھ سو میل سمجھنا چاہیئے.ابن سعد جلد ۲ صفحه ۵۶ وزرقانی جلد ۲ حالات سریہ قمر کا
: زرقانی حالات سریہ فخر کا
۵: اصابه جلد اصفحه ۴۱۲
: ابن سعد جلد ۵ صفحه ۴۰۱
Page 765
۷۵۰
مدینہ پہنچ کر جب ثمامہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی
پہچان لیا اور محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں سے فرمایا.جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے لاعلمی
کا اظہار کیا جس پر آپ نے ان پر حقیقت حال ظاہر کی.اس کے بعد آپ نے حسب عادت ثمامہ کے
ساتھ نیک سلوک کئے جانے کا حکم دیا اور پھر اندرون خانہ تشریف لے جا کر گھر میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ
کھانے کے لئے تیار ہو شمامہ کے لئے باہر بھجوا دو اس کے ساتھ ہی آپ نے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ
ثمامہ کو کسی دوسرے مکان میں رکھنے کی بجائے مسجد نبوی کے صحن میں ہی کسی ستون کے ساتھ باندھ کر قید رکھا
جائے جس سے آپ کی غرض یہ تھی کہ تا آپ کی مجالس اور مسلمانوں کی نماز میں شمامہ کی آنکھوں کے سامنے
منعقد ہوں اور اس کا دل ان روحانی نظاروں سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہو جائے.ان ایام میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح کے وقت ثمامہ کے قریب تشریف لے جاتے
اور حال پوچھ کر دریافت فرماتے کہ تمامہ ! بتاؤ اب کیا ارادہ ہے ؟ تمامہ جواب دیتا اے محمد ! (صلی اللہ
علیہ وسلم ) اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کو اس کا حق ہے کیونکہ میرے خلاف خون
کا الزام ہے لیکن اگر آپ
احسان کریں تو آپ مجھے شکر گزار پائیں گے اور اگر آپ فدیہ لینا چاہیں تو میں فدیہ دینے کے لئے بھی تیار
ہوں.تین دن تک یہی سوال و جواب ہوتا رہا.آخر تیسرے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود
صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ثمامہ کو کھول کر آزاد کر دو.“ صحابہؓ نے فوراً آزاد کر دیا اور ثمامہ جلدی جلدی
مسجد سے نکل کر باہر چلا گیا.غالباً صحابہ یہ سمجھے ہوں گے کہ اب وہ اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائے گا
مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ ثمامہ کا دل مفتوح ہو چکا ہے.چنانچہ وہ ایک قریب کے باغ
میں گیا اور وہاں سے نہا دھو کر واپس آیا اور آتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا.اس کے بعد اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا.'یا رسول اللہ ایک وقت تھا کہ مجھے تمام
دنیا میں آپ کی ذات سے اور آپ کے دین سے اور آپ کے شہر سے سب سے زیادہ دشمنی تھی لیکن اب
مجھے آپ کی ذات اور آپ کا دین اور آپ کا شہر سب سے زیادہ محبوب ہیں..اس دن شام کو جب حسب دستور ثمامہ کے لئے کھانا آیا تو اس نے تھوڑا سا کھانا کھا کر چھوڑ دیا.جس
پر صحابہ نے تعجب کیا کہ آج صبح تک تو ثمامہ بہت زیادہ کھاتا رہا ہے اور گویا پیٹو تھا لیکن اب اس نے بہت
ا: ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۱
۲: زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۴۵
بخاری کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ و مسلم کتاب الجہاد باب ربط الاسیر
Page 766
۷۵۱
تھوڑا کھانا کھایا ہے.یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا.صبح تک شمامہ
کافروں کی طرح کھانا کھاتا تھا اور اب اس نے ایک مسلمان کی طرح کھایا ہے.“ اور آپ نے اس کی
تشریح یوں فرمائی کہ ” کا فرسات آنتوں میں کھانا کھاتا ہے مگر مسلمان صرف ایک آنت میں کھاتا ہے.“
اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ جہاں ایک کا فرتو دنیوی لذات میں انہاک ہوتا ہے اور گویاوہ اسی میں غرق
رہتا ہے وہاں ایک سچا مسلمان اپنی جسمانی ضروریات کو صرف اس حد تک محدود رکھتا ہے جو زندگی کے
قیام کے لئے ضروری ہے کیونکہ اسے حقیقی لذت صرف دین میں حاصل ہوتی ہے.یہ بھی یادرکھنا چاہئے کہ
اس جگہ سات کے عدد سے حسابی عدد مراد نہیں ہے بلکہ عربی محاورہ کی رو سے سات کا عدد کثرت اور تکمیل
کے اظہار کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.گویا مراد یہ ہے کہ ایک کا فرد نیوی لذات میں غرق رہتا ہے اور
اس کی ساری توجہ دنیا میں صرف ہوتی ہے مگر ایک مومن اپنے آپ کو دنیوی لذات سے روک کر رکھتا ہے اور
ضرورت حقہ کی حد سے آگے نہیں گزرتا کیونکہ اس کی حقیقی لذات کا میدان اور ہے.یہ تعلیم آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے فطری میلان اور آپ کے ذاتی خلق کا ایک نہایت سچا آئینہ ہے.مسلمان ہونے کے باعث ثمامہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول
اللہ ! جب آپ
کے آدمیوں نے مجھے قید کیا تھا تو اس وقت میں خانہ کعبہ کے عمرہ کے لیے جا رہا تھا اب مجھے کیا ارشاد
ہے؟ آپ نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی اور دُعا کی اور ثمامہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا.وہاں پہنچ کر
ثمامہ نے جوشِ ایمان میں قریش کے اندر بر ملا تبلیغ شروع کر دی.قریش نے یہ نظارہ دیکھا تو اُن کی
آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے ثمامہ کو پکڑ کر ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں.مگر پھر یہ سوچ کر کہ وہ
یمامہ کے علاقے کا رئیس ہے اور یمامہ کے ساتھ مکہ کے گہرے تجارتی تعلقات ہیں وہ اس ارادہ سے باز
آگئے اور ثمامہ کو برا بھلا کہہ کر چھوڑ دیا مگر شمامہ کی طبیعت میں سخت جوش تھا اور قریش کے وہ مظالم جو وہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کرتے رہے تھے وہ سب ثمامہ کی آنکھوں کے سامنے تھے.اس نے مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے قریش سے کہا.” خدا کی قسم آئندہ یمامہ کے علاقہ سے تمہیں غلہ کا
ا: ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۱
س : عمرہ حج کی ایک قسم ہے جس میں حج کے بعض مراسم اور شرائط کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے.یہ ایک نفلی عبادت ہے جس
کی ادائیگی فرائض میں داخل نہیں.آج کل انگریزی محاورہ میں اسے چھوٹا حج کہتے ہیں
بخاری ومسلم
تاج العروس
۵: ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۲
Page 767
۷۵۲
ایک دانہ نہیں آئے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں گے.اپنے وطن میں پہنچ کر ثمامہ نے واقعی ملکہ کی طرف یمامہ کے قافلوں کی آمد ورفت روک دی اور چونکہ
مکہ کی خوراک کا بڑا حصہ یمامہ کی طرف سے آتا تھا اس لئے اس تجارت کے بند ہو جانے سے قریش مکہ
سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے گھبرا کر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا کہ آپ ہمیشہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ہم آپ کے بھائی بند ہیں.ہمیں
اس مصیبت سے نجات دلائیں." اس وقت قریش مکہ اس قد رگھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے صرف
اس خط پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اپنے رئیس ابوسفیان بن حرب کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بھجوایا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زبانی بھی بہت آہ و پکار کی اور اپنی
مصیبت کا اظہار کر کے رحم کا طالب ہوا.جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو ہدایت
بھجوادی کہ قریش کے ان قافلوں کی جن میں اہل مکہ کی خوراک کا سامان ہوروک تھام نہ کی جاوے.چنانچہ اس تجارت کا سلسلہ پھر جاری ہو گیا اور مکہ والوں کو اس مصیبت سے نجات ملی.یہ واقعہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شفقت اور رحم اور عفو کا ایک بین ثبوت ہے وہاں
اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ شروع شروع میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلوں
کی روک تھام کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کی اصل غرض و غایت یہ نہیں تھی کہ قریش کو قحط میں مبتلا کر کے
تباہ کیا جائے بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے قرب و جوار کو قریش کے خطرہ سے محفوظ کر لیا جائے.اس واقعہ سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیم کی رو سے حربی دشمن کے متعلق بھی یہ بات پسندیدہ
نہیں ہے کہ عام حالات میں اس کے سلسلہ رسل و رسائل کو اس حد تک بند کر دیا جائے کہ وہ نان جویں تک
سے محروم ہو جائے.ہاں سامان حرب کی آمد و رفت یا ضروری سامان خور و نوش کے علاوہ دوسری اشیاء
کی برآمد و درآمد کا سلسلہ جنگی ضروریات کے ماتحت روکا جاسکتا ہے اور اگر یہ صورت ہو کہ دشمن مسلمانوں کی
خوراک کے سلسلہ کو روکے تو پھر قرآن کی اصولی تعلیم جز و ا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا" کے ماتحت اس کے
اس سلسلہ کو بھی روکنا جائز ہوگا.جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے ثمامہ بن اثال اپنے علاقہ کا ایک ذی اثر رئیس تھا.اس کی پر جوش تبلیغ کے
بخاری ومسلم
سے نسائی و حاکم و بیہقی بحوالہ زرقانی جلد۲ صفحه ۱۴۶ حالات سریہ قرطا
: ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۲
: سورة الشورى : ۴۱
Page 768
۷۵۳
ذریعہ یمامہ کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے.اس کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے قریب اور حضرت ابوبکر کی خلافت کے شروع میں مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے پیچھے
لگ کر یمامہ کے بہت سے بادیہ نشین اسلام سے مرتد ہو گئے تو تمامہ نہ صرف خود نہایت پختگی کے ساتھ
اسلام پر قائم رہا بلکہ اس نے اپنی والہا نہ جدو جہد سے بہت سے لوگوں کو مسیلمہ کے شر سے محفوظ کر کے
اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع رکھا اور مسیلمہ کے فتنہ کے مٹانے میں نمایاں خدمات سرانجام دیں لے
غزوہ عکاشہ بن محصن ربیع الاول ۶ ہجری اسی سال ماہ ربیع الاول میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے ایک مہاجر صحابی عکاشہ بن محصن کو چالیس
مسلمانوں پر افسر بنا کر قبیلہ بنی اسد کے مقابلہ کے لئے روانہ فرمایا.یہ قبیلہ اس وقت ایک چشمہ کے قریب
ڈیرہ ڈالے پڑا تھا جس کا نام عمر تھا جو مدینہ سے مکہ کی سمت میں چند دن کے فاصلہ پر واقع تھا.عکاشہ کی
پارٹی جلدی جلدی سفر کر کے غمر پہنچی تا کہ انہیں شرارت سے روکا جاسکے تو معلوم ہوا کہ قبیلہ کے لوگ
مسلمانوں کی خبر پا کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے.اس پر عکاشہ اور اس کے ساتھی مدینہ کی طرف واپس
لوٹ آئے اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی.سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے عکاشہ فضلا صحابہ میں سے تھے اور اہل مکہ
کے حلیف تھے.وہ حضرت ابوبکرؓ کے عہد
ستر ہزار آدمی بلاحساب جنت میں جائیں گے میں جنگ مرتدین میں شہید ہوئے.تم میہ
وہی بزرگ ہیں جن کے متعلق حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس
میں ذکر فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے یعنی
وہ ایسے روحانی مرتبہ پر فائز ہوں گے اور ان کے لئے خدائی فضل و کرم اس قدر جوش میں ہوگا کہ ان کے
حساب کتاب کی ضرورت نہیں سمجھی جائے گی.اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کے چہرے قیامت
کے دن اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح کہ چودہویں رات کا چاند آسمان پر چمکتا ہے.اس پر عکاشہ
نے عرض کیا.یا رسول اللہ ! دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے.آپ نے اسی
وقت دعا فرمائی کہ اے خدا تو اپنے فضل سے عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں سے کر دے.اس کے بعد ایک
: طبقات ابن سعد واسد الغابہ حالات معمامہ بن اثال و زرقانی حالات سریہ قرطا
یہ نام عکاشہ یعنی کاف کی تشدید سے بھی آتا ہے
: ابن سعد
اسدالغابه
Page 769
۷۵۴
انصاری شخص نے عرض کیا.یا رسول اللہ ! میرے لئے بھی یہ دعا فرمائیں اس پر آپ نے فرمایا:
سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ
یعنی اب تو عکاشہ تم پر اس معاملہ میں بازی لے جاچکا ہے.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا یہ ایک بظاہر چھوٹا سا واقعہ اپنے اندر بہت سے معارف کا خزانہ
رکھتا ہے کیونکہ اول تو اس سے یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا اس درجہ فضل و کرم ہے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض اس کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ آپ کی امت میں سے ستر ہزار
آدمی ایسا ہو گا جو اپنے نمایاں روحانی مقام اور خدا کے خاص فضل وکرم کی وجہ سے گویا قیامت کے دن
حساب و کتاب کی پریشانی سے بالا سمجھا جائے گا.دوسرے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسا قرب حاصل ہے کہ آپ کی روحانی توجہ پر خدا تعالیٰ نے فوراً بذریعہ
کشف یا القاء آپ کو یہ علم دے دیا کہ عکاشہ بھی اس ستر ہزار کے پاک گروہ میں شامل ہے اور یہ بھی ممکن
ہے کہ عکاشہ پہلے اس گروہ میں شامل نہ ہو مگر آپ کی دعا کے نتیجہ میں خدا نے اسے یہ شرف عطا کر دیا ہو.تیسرے اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا اس درجہ ادب ملحوظ تھا
اور آپ اپنی امت میں جہد و عمل کو اس درجہ ترقی دینا چاہتے تھے کہ جب عکاشہ کے بعد ایک دوسرے شخص
نے آپ سے اسی قسم کی دعا کی درخواست کی تو آپ نے اس اخص روحانی مقام کے پیش نظر جو اس پاک گروہ
کو حاصل ہے مزید انفرادی دعا سے انکار کر دیا تا کہ مسلمانوں کو تقویٰ اور ایمان اور عمل صالح میں ترقی
کرنے کی طرف توجہ رہے.چوتھے اس سے آپ کے اعلیٰ اخلاق پر بھی غیر معمولی روشنی پڑتی ہے کیونکہ
آپ نے انکار ایسے رنگ میں نہیں کیا.جس سے سوال کرنے والے انصاری کی دل شکنی ہو بلکہ ایک
نہایت لطیف رنگ میں بات کو ٹال گئے.سریہ محمد بن مسلمہ بطرف ذوالقصہ ربیع الآخر ۶ ہجری ربيع الآخر کے مہینہ میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ
انصاری کو ذوالقصہ کی طرف روانہ فرمایا جو مدینہ سے چوبیس میل کے فاصلہ پر تھا اور جہاں ان ایام میں
: بخاری کتاب الرقاق باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُونَ الْفَا بِغَيْرِ حِسَابِ
: یہ بھی ممکن ہے کہ ستر ہزار سے معین تعداد مراد نہ ہو، بلکہ غیر معمولی طور پر بھاری جماعت مراد ہو.کیونکہ عربی زبان
میں ستر کا لفظ بھاری کثرت یا کامل تعداد کے اظہار کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.
Page 770
۷۵۵
بنو ثعلبہ آباد تھے.محمد بن مسلمہ اور ان کے دس ساتھی رات کے وقت وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس قبیلہ کے
ایک سونو جوان جنگ کے لئے تیار بیٹھے ہیں.صحابہ کی جماعت سے یہ پارٹی تعداد میں دس گنے زیادہ تھی
مگر تعداد کا فرق اسلامی ضابطہ حرب میں چنداں قابل لحاظ نہیں تھا.محمد بن مسلمہ نے فوراً اس لشکر کے
سامنے صف آرائی کر لی اور فریقین کے درمیان رات کی تاریکی میں خوب تیراندازی ہوئی.اس کے بعد
کفار نے صحابہ کی اس مٹھی بھر جماعت پر دھاوا بول دیا اور چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک آن کی آن
میں یہ دس فدایان اسلام خاک پر تھے.محمد بن مسلمہ کے ساتھی تو سب کے سب شہید ہو گئے مگر خود
محمد بن مسلمہ بچ گئے کیونکہ کفار نے انہیں دوسروں کی طرح مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور ان کے کپڑے وغیرہ
اتار کر لے گئے.غالباً محمد بن مسلمہ بھی وہاں پڑے پڑے فوت ہو جاتے مگر حسن اتفاق سے ایک مسلمان
کا وہاں سے گزر ہو گیا اور اس نے محمد بن مسلمہ کو پہچان کر انہیں اٹھا کر مدینہ پہنچادیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے ابو عبیدہ بن الجراح کو جو قریش
میں سے تھے اور کبار صحابہ میں شمار ہوتے تھے محمد بن مسلمہ کے انتقام کے لئے ذوالقصہ کی طرف روانہ فرمایا
اور چونکہ اس عرصہ میں یہ بھی اطلاع موصول ہو چکی تھی کہ قبیلہ بنو ثعلبہ کے لوگ مدینہ کے مضافات پر حملہ
کا ارادہ رکھتے ہیں اس لئے آپ نے ابو عبیدہ کی کمان میں چالیس مستعد صحابہ کی جماعت بھجوائی اور حکم
دیا کہ راتوں رات سفر کر کے صبح کے وقت وہاں پہنچ جائیں.ابوعبیدہ نے تعمیل ارشاد میں یلغار کر کے
عین صبح کی نماز کے وقت انہیں جاد بایا اور وہ اس اچانک حملہ سے گھبرا کر تھوڑے سے مقابلہ کے بعد
بھاگ نکلے اور قریب کی پہاڑیوں میں غائب ہو گئے.ابو عبیدہ نے مال غنیمت پر قبضہ کیا اور مدینہ کی
طرف واپس لوٹ آئے ہے
اس مہم میں جن دو صحابہ کا ذکر ہے یعنی محمد بن مسلمہ اور ابو عبیدہ بن الجراح وہ دونوں کبار صحابہ میں سے
تھے.محمد بن مسلمہ اپنے ذاتی اوصاف اور قابلیت کے علاوہ قتل کعب بن اشرف یہودی کے ہیرو تھے کیونکہ
یہ مفسدا نہی کے ہاتھ سے اپنے کیفر کردار کو پہنچا تھا.محمد بن مسلمہ انصار کے
قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور
حضرت عمر کی خلافت میں ان کے خاص معتمد سمجھے جاتے تھے.چنانچہ حضرت عمر عموماً انہی کو اپنے عمال کی
شکایتوں کی تحقیق کے لئے بھجوایا کرتے تھے.حضرت عثمان کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں اندرونی
فتنوں کا دروازہ کھلا تو محمد بن مسلمہ نے اپنی تلوار کو ایک پتھر پر تو ڑ کر اپنے ہاتھ میں صرف ایک چھڑی لے لی
ابن سعد جلد ۲ حالات سریہ ذوالقصه
Page 771
۷۵۶
اور جب کسی نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہی سنا ہوا
ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر باہمی قتل و غارت کا دروازہ کھلےتو تم تلوار کوتو ڑ کر گھر میں اس طرح دبک کر
بیٹھ جانا جس طرح کسی کمرہ میں اس کا فرش پڑا ہوا ہوتا ہے.یہ حکم غالباً محمد بن مسلمہ کے لئے یا اس فتنہ
کے لئے خاص تھا ورنہ بعض اوقات اندرونی فتنوں کا مقابلہ بھی ایک اعلیٰ دینی خدمت کا رنگ رکھتا ہے.دوسرے صحابی ابوعبیدہ بن الجراح تھے.یہ چوٹی کے صحابہ میں سے تھے اور قریشی تھے.ان کی رفعت
شان اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الملت کا خطاب عطا فرمایا تھا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے جن دو صحابہ کو خلافت کا اہل سمجھا تھا ان میں
سے ایک یہ بھی تھے.ابو عبیدہ حضرت عمرؓ کے عہد میں مرض طاعون سے وفات پا کر شہید ہوئے.سریہ زید بن حارثہ بطرف بنی سلیم.ربیع الآخر 4 ہجری اسی ماہ ربیع الآخر 4 ہجری میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
آزاد کردہ غلام اور سابق منیشی زید بن حارثہ کی امارت میں چند مسلمانوں
کو قبیلہ بنی سلیم کی طرف روانہ
فرمایا.یہ قبیلہ اس وقت نجد کے علاقہ میں بمقام جموم آباد تھا اور ایک عرصہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے خلاف برسر پیکار چلا آتا تھا.چنانچہ غزوہ خندق میں بھی اس قبیلہ نے مسلمانوں کے خلاف نمایاں حصہ
لیا تھا.جب زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی جموم میں پہنچے جو مدینہ سے قریباً پچاس میل کے فاصلہ پر تھا تو
اسے خالی پایا.مگر انہیں قبیلہ مزینہ کی ایک عورت حلیمہ نامی سے جو مخالفین اسلام میں سے تھی اس جگہ کا
پتہ لگ گیا جہاں اس وقت قبیلہ بنو سلیم کا ایک حصہ اپنے مویشی چرارہا تھا.چنانچہ اس اطلاع سے فائدہ
اٹھا کر زید بن حارثہ نے اس جگہ پر چھاپا مارا.اس اچانک حملہ سے گھبرا کر اکثر لوگ تو ادھر ادھر بھاگ کر
منتشر ہو گئے مگر چند قیدی اور مویشی مسلمانوں کے ہاتھ آگئے جنہیں وہ لے کر مدینہ کی طرف واپس لوٹ
آئے.اتفاق سے ان قیدیوں میں حلیمہ کا خاوند بھی تھا اور ہر چند کہ وہ حربی مخالف تھا.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے حلیمہ کی اس امداد کی وجہ سے نہ صرف حلیمہ کو بلا فدیہ آزاد کر دیا بلکہ اس کے خاوند کو بھی احسان
کے طور پر چھوڑ دیا اور حلیمہ اور اس کا خاوند خوشی خوشی اپنے وطن کو واپس چلے گئے.ہے
ا
لے اسد الغابہ حالات محمد بن مسلمہ
: زرقانی
: اسدالغابہ زیر نام ابوعبیده
: ابن سعد جلد ۲
Page 772
۷۵۷
سریہ زید بن حارثہ بطرف عیص.جمادی الاولی ۶ ہجری زید بن حارثہ کو اس مہم سے
واپس آئے زیادہ دن نہیں
گزرے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولیٰ کے مہینہ میں انہیں ایک سو ستر صحابہ کی کمان
میں پھر مدینہ سے روانہ فرمایا.اس مہم کی وجہ اہل سیر نے یہ کھی ہے کہ شام کی طرف سے قریش مکہ کا ایک
قافلہ آرہا تھا اس کی روک تھام کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستہ کو روانہ فرمایا تھا.قافلوں کی
روک تھام کے متعلق ہم غزوات کے ابتدا میں ایک اصولی بحث درج کر چکے ہیں.اس جگہ اس کے اعادہ
کی ضرورت نہیں.صرف اس قدر اشارہ کافی ہے کہ قریش کے قافلے ہمیشہ مسلح ہوتے تھے اور مکہ اور شام
کے درمیان آتے جاتے ہوئے وہ مدینہ کے بالکل قریب سے گزرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی طرف سے
ہر وقت خطرہ رہتا تھا.علاوہ ازیں جیسا کہ ابتدائی بحث میں ذکر کیا جا چکا ہے یہ قافلے جہاں جہاں سے
گزرتے تھے.قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے جاتے تھے.جس کی وجہ سے سارے ملک میں
مسلمانوں کے خلاف عداوت کی ایک خطر ناک آگ مشتعل ہو چکی تھی اس لئے ان کی روک تھام ضروری
تھی.بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ کی خبر پا کر زید بن حارثہ کو اس طرف روانہ فرمایا اور وہ
اس ہوشیاری سے گھات لگاتے ہوئے بڑھے کہ بمقام عیص قافلہ کو جا دبایا.عیص ایک جگہ کا نام ہے جو
مدینہ سے چار دن کی مسافت پر سمندر کی جانب واقع ہے چونکہ یہ اچانک حملہ تھا اہل قافلہ مسلمانوں کے حملہ
کی تاب نہ لا سکے اور اپنے ساز وسامان کو چھوڑ کر بھاگ نکلے.زید نے بعض قیدی پکڑ کر اور سامان قافلہ
اپنے قبضہ میں لے کر مدینہ کی راہ لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داما دابو العاص کا مسلمان ہونا ان قیدیوں میں جو سریہ
داماد
بطرف عیص میں پکڑے
گئے ابوالعاص بن الربیع بھی تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت خدیجہ مرحومہ کے
قریبی رشتہ داروں میں سے تھے.اس سے قبل وہ جنگ بدر میں بھی قید ہو کر آئے تھے مگر اس وقت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ مکہ پہنچ کر آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو
مدینہ بھجوادیں.ابوالعاص نے اس وعدہ کو تو پورا کر دیا تھا مگر وہ خود بھی تک شرک پر قائم تھے.جب زید
بن حارثہ انہیں قید کر کے مدینہ میں لائے تو رات کا وقت تھا مگر کسی طرح ابوالعاص نے حضرت زینب کو
ل : دیکھئے سیرۃ خاتم النبین حصہ دوم
: ابن سعد جلد ۲
Page 773
۷۵۸
اطلاع بھجوادی کہ میں اس طرح قید ہو کر یہاں پہنچ گیا ہوں تم اگر میرے لئے کچھ کرسکتی ہو تو کرو.چنانچہ عین اس وقت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صبح کی نماز میں مصروف تھے زینب
نے گھر کے اندر سے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ ”اے مسلمانو! میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا.جو کچھ زینب نے کہا
ہے وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا.واللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا.مگر مومنوں کی جماعت ایک جان کا حکم رکھتی
ہے اگر ان میں سے کوئی کسی کافر کو پناہ دے تو اس کا احترام لازم ہے.پھر آپ نے زینب کی طرف
166
متوجہ ہو کر فرمایا ” جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں.اور جو مال اس مہم میں ابو العاص سے
حاصل ہوا تھا وہ اسے لوٹا دیا.پھر آپ گھر میں تشریف لائے اور اپنی صاحبزادی زینب سے فرمایا ”ابوالعاص
کی اچھی طرح خاطر تواضع کرو.مگر اس کے ساتھ خلوت میں مت ملو کیونکہ موجودہ حالت میں تمہارا اس کے
ساتھ ملنا جائز نہیں ہے.چند روز مدینہ میں قیام کر کے ابو العاص مکہ کی طرف واپس چلے گئے مگر اب ان کا
مکہ میں جانا وہاں ٹھہرنے کی غرض سے نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بہت جلد اپنے لین دین سے فراغت حاصل
کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
پہنچ کر مسلمان ہو گئے.جس پر آپ نے حضرت زینب کو ان کی طرف بغیر کسی جدید نکاح کے لوٹا دیا یعنی
زینب کو اجازت دے دی کہ اب وہ ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھ سکتی ہیں..بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب اور ابو العاص کا دوبارہ نکاح پڑھا گیا تھا
مگر پہلی روایت زیادہ مضبوط اور صحیح ہے."
ایک مسلمان اور کافر کے ازدواجی تعلق کے متعلق اسلامی تعلیم اس جگہ ضمنا یہ ذکر خالی از
فائدہ نہ ہوگا کہ ایک
مسلمان اور کافر کے باہمی نکاح کے بارے میں قرآنی احکام تین مختلف موقعوں پر درجہ بدرجہ نازل ہوئے
ہیں.سب سے پہلے ہجرت کے کچھ عرصہ بعد سورۃ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں یہ حکم دیا گیا کہ کوئی.مراد یہ ہے کہ عام حالات میں ایسا ہونا چاہئے ورنہ خاص حالات میں جب کہ مثلا کسی بالا افسر کا کوئی اور حکم موجود ہو
یا پناہ دینے والا بد نیتی یا فساد کی غرض سے یہ طریق اختیار کرے وغیر ذالک تو ایسے حالات میں یہ فعل جائز نہیں سمجھا جائے
گا.واللہ اعلم
طبقات ابن سعد وزرقانی حالات سریہ عیص
ابوداؤ دوتر مذی وابن ماجه
زرقانی
Page 774
۷۵۹
مسلمان کسی مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اور نہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی مشرک مرد کے
ساتھ ہوسکتا ہے.چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے.لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا تَتَّكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوال
یعنی ”اے مسلمانو ! تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان
ہو جائیں اور نہ ہی تم مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ کیا کر وحتی کہ وہ مسلمان
ہو جائیں.“
لیکن اس حکم میں یہ تصریح نہیں تھی کہ اگر نکاح پہلے سے ہو چکا ہوتو پھر کیا کیا جائے.سواس کے متعلق
صلح حدیبیہ کے بعد سورۃ ممتحنہ والی آیات نازل ہوئیں جن میں یہ حکم دیا گیا کہ ایک مسلمان عورت کا کسی
صورت میں بھی ایک مشرک مرد کے ساتھ نکاح قائم نہیں رہ سکتا اور نہ کسی مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ
وہ کسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھے.چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنُتُ مُهْجِرْتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ
حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ....وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
یعنی اے مسلمانو! اگر تمہارے پاس مومن عورتوں میں سے بعض عورتیں ہجرت کر کے
پہنچیں تو تم انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد وہ کافروں کے لئے
جائز نہیں رہیں.اور نہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لئے جائز ہیں...اور اگر اے
مسلمانو! تمہارے نکاح میں کوئی کافر (مشرک) عورت ہو تو تم اس کے عقد نکاح کو بھی قائم
نہیں رکھ سکتے.“
66
اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں سورۃ مائدہ والی آیات نازل
ہوئیں.جن میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ ایک اہل کتاب عورت (یعنی یہودی یا عیسائی وغیرہ) کے
ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے.چنانچہ قرآن شریف فرماتا ہے:
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ والمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
یعنی ”اے مسلمانو! آج کے دن تمہارے لئے تمام پاکیزہ چیز میں حلال قرار دی گئی ہیں.....ل : سورة البقرة : ۲۲۲
: سورۃ الممتحنه : 11
سے : سورة المائدة : ۶
Page 775
Page 776
271
یہ ایک معلق قسم کی صورت تھی یعنی اگر اس عرصہ میں حضرت زینب کا دوسری جگہ نکاح ہو جا تا تو وہ جائز تھا
لیکن چونکہ وہ ابھی تک آزاد تھیں اس لئے سابقہ خاوند کے مسلمان ہونے پر انہیں اس کی طرف بلا نکاح
لوٹا دیا گیا.اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک مفقود الخبر انسان کی ہوتی ہے جس پر ایک معین عرصہ
گزرنے پر اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کے لئے آزاد ہو جاتی ہے.لیکن اگر قبل شادی
اس کا اصل خاوند آ جائے تو سابقہ نکاح ہی قائم رہتا ہے.واللہ اعلم
اس ضمن میں اس حکمت کا بیان کرنا بھی مناسب ہوگا کہ اسلام میں غیر مسلم مرد کے نکاح میں مسلمان
لڑکی کا دینا یا مسلمان مرد کے نکاح میں غیر اہل کتاب کی لڑکی لینا کیوں حرام قرار دیا گیا.سو جاننا چاہئے کہ
مقدم الذکر صورت یعنی غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو غیر مسلم
مرد کی شادی میں دینے کے یہ معنی ہیں کہ لڑکی کے دین کو خود اپنے ہاتھ سے خطرہ میں ڈالا جاوے اور اسلام
کو ترقی دینے کی بجائے اس کے تنزل کا راستہ کھولا جائے جسے اسلام کسی صورت میں برداشت نہیں
کر سکتا.اور غیر اہل کتاب کا فر کی لڑکی لینے سے اس لئے روکا گیا ہے کہ چونکہ ایسی لڑکی اصول مذہب سے
بالکل بے بہرہ ہوگی اس لئے وہ نہ صرف بچوں کی تربیت کے لحاظ سے خطر ناک ہوگی بلکہ خاوند کے ساتھ
بھی اگر وہ سچا مسلمان ہے اس کا دل نہیں مل سکے گا اور خانگی زندگی حقیقی خوشی سے محروم رہے گی.اس کے
مقابل پر اہل کتاب کی لڑکی لینے کی اجازت دینے میں یہ مصلحت ہے کہ اول تو بین الاقوام تعلقات کی
توسیع کا راستہ کھلا رہے دوسرے ایسی لڑکی اصول مذہب سے واقف ہونے کی وجہ سے ایک حد تک
بچوں کی تربیت میں مد ہو سکتی ہے اور تیسرے یہ کہ اس کے لئے خاوند کے مشفقانہ اثر کے ماتحت اسلام کی
طرف کھنچے آنے کی زیادہ توقع کی جاسکتی ہے.واللہ اعلم
مگر بایں ہمہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن وحدیث دونوں میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اہل کتاب کی
لڑکی کے ساتھ شادی کرنا بھی اسلام میں ایک استثنائی رنگ رکھتا ہے جس کی صرف خاص حالات کے
ماتحت خاص مصالح کے پیش نظر اجازت دی گئی ہے اور عام حالات میں بہتر یہی سمجھا گیا ہے کہ مسلمان
مرد کا نکاح حتی الوسع مسلمان عورت کے ساتھ ہوا
ابوالعاص کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ا: سورة البقرة : ۲۲۲ وسورة نور : ۳۳ و بخاری کتاب النکاح
Page 777
۷۶۲
کے داماد ابوالعاص بن الربیع حضرت خدیجہ مرحومہ کے قریبی رشتہ دار یعنی حقیقی بھانجے تھے اور باوجود
مشرک ہونے کے ان کا سلوک اپنی بیوی سے بہت اچھا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی میاں بیوی کے
تعلقات بہت خوشگوار رہے.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت سے ابوالعاص کی بہت تعریف
فرمایا کرتے تھے کہ اس نے میری لڑکی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے.ابوالعاص حضرت ابوبکر کے
عہد خلافت میں ۱۲ ہجری میں فوت ہوئے مگر ان کی زوجہ محترمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی
فوت ہو گئیں.ان کی لڑکی امامہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھی.حضرت فاطمہ کی وفات کے
بعد حضرت علی کے نکاح میں آئیں مگر اولاد سے محروم رہیں.غز وہ بنو لحیان جمادی الا ولی ۶ ہجری مطابق ستمبر ۶۲۷ء اصحاب رجیع کا المناک واقعہ ۴ ھ کے
واقعات میں بیان کیا جا چکا ہے.اس
موقع پر دس بے گناہ مسلمان جو اسلام کی پر امن تبلیغ کے لئے بھجوائے گئے تھے نہایت بے دردی اور دھو کے
کے ساتھ قتل کر دئے گئے تھے اور اس سارے فتنہ کی تہ میں بنولحیان کا ہاتھ تھا جو اس زمانہ میں مکہ اور مدینہ
کے درمیان وادی غران میں آباد تھے.طبعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا سخت صدمہ تھا اور چونکہ
بنو لحیان کا رویہ ابھی تک اسی طرح معاندانہ اور مفسدا نہ تھا اور ان کی طرف سے آئندہ کے لئے بھی اندیشہ
تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی مزید فتنہ انگیزی کا باعث نہ بنیں اس لئے آپ نے انتظامی لحاظ سے
مناسب خیال
فرمایا کہ ان کی کسی قدر گوشمالی ہو جائے تا کم از کم آئندہ کے لئے مسلمان ان کے فتنوں سے
محفوظ ہو جائیں اس خیال سے آپ دوسو صحابہ کی جمعیت کو ساتھ لے کر ماہ جمادی الاولی ۶ ھ میں مدینہ سے
نکلے.اور اس خیال سے کہ اس سفر کی غرض و غایت مخفی رہے تا کہ بنولحیان خبر پا کر ہوشیار نہ ہو جائیں.آپ نے مدینہ سے نکل کر شروع شروع میں شمال کا رخ کیا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جنوب کی
طرف گھوم گئے.مگر باوجود اس احتیاط کے دشمن کسی طرح خبر پا کر ہوشیار ہو چکا تھا اور پیشتر اس کے کہ
آپ وادی غران میں پہنچتے بنواھیان کے لوگ اردگرد کی پہاڑیوں میں منتشر ہو کر غائب ہو چکے تھے.آپ نے منزل مقصود پر پہنچ کر وہاں کچھ وقت قیام فرمایا اور روایت آتی ہے کہ جب اس سفر میں آپ
لے بخاری ابواب مناقب
طبقات ابن سعد حالات ابوالعاص و زرقانی حالات حضرت زینب
ابن ہشام وطبری حالات غزوہ بنواھیان.ابن سعد اس نے غزوہ کی تاریخ ربیع الاول بیان کی ہے.واللہ اعلم
ابن سعد وابن ہشام
ابن ہشام
Page 778
۷۶۳
اس مقام پر پہنچے جہاں آپ کے صحابہ شہید کئے گئے تھے تو آپ پر سخت رقت طاری ہوگئی اور آپ نے
نہایت الحاح کے ساتھ ان شہداء کے لئے دعا مانگی یا پھر آپ مقام عسفان کی طرف آگے بڑھے جواس
جگہ سے پانچ چھ میل کے فاصلہ پر مکہ کی جانب واقع تھا اور اپنے اصحاب کی متفرق پارٹیاں ادھر ادھر روانہ
فرمائیں جن میں سے ایک پارٹی کے امیر حضرت ابو بکر بھی تھے جو مکہ کی سمت میں بھیجی گئی تھی مگر
ان میں سے کسی پارٹی کو بھی لڑائی پیش نہیں آئی اور چند دن کی غیر حاضری کے بعد آپ مدینہ میں واپس
تشریف لے آئے.سفر سے واپسی کی دعا واپسی سفر کے دوران میں آپ نے ایک دعا فرمائی جسے بعد میں مسلمان
اپنے اہم سفروں سے واپسی کے موقع پر عموماً پڑھا کرتے تھے.وہ دعا یہ ہے:
آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ -
یعنی ” ہم لوگ اپنے خدا کی طرف لوٹنے والے ہیں.اسی کی طرف جھکنے والے.اسی کی
عبادت کرنے والے.اسی کے سامنے گرنے والے اور اپنے رب
کی تعریف کے گیت گانے والے.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے بعد کے سفروں میں عموماً یہ دعا فرمایا کرتے تھے اور بعض
اوقات اس کے ساتھ یہ الفاظ زیادہ فرماتے تھے کہ:
صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
یعنی ”ہمارے خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی نصرت فرمائی اور دشمن کے
،،
لشکروں کو خود اپنے دم سے پسپا کر دیا “.یہ دعا جوغز وہ بنولحیان کے تعلق میں اہل سیر نے بیان کی ہے اور محدثین نے بھی اس کی تصدیق کی ہے
اپنے اندر ایک خاص کیفیت کی حامل ہے اور اس کے مطالعہ سے ان جذبات کے اندازہ کرنے کا موقع ملتا
ہے جو اس پر آشوب زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فداہ نفسی کے قلب مطہر میں موجزن تھے اور
جنہیں آپ اپنے صحابہ کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے.اس دعا میں یہ تڑپ مخفی ہے کہ دشمن کی طرف سے
جوروک مسلمانوں کی عبادت گزاری اور اسلام کی پر امن تبلیغ کے رستے میں ڈالی جارہی ہے اللہ تعالیٰ
اسے دور فرمائے اور جس حد تک
اللہ تعالیٰ نے اس روک کو دور کیا ہے اس پر شکر گزاری کا گیت گایا گیا ہے.ابن سعد
: ابن ہشام طبری و ابن سعد
سے بخاری کتاب الجہاد باب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزُوِوَبَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا -
Page 779
۷۶۴
اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اپنے ایک نہایت دل پسند کام میں منہمک ہو اور پھر یکلخت کوئی دوسرا
شخص اس کے کام میں مخل ہو کر اس کی توجہ کومنتشر کر دے.مگر کچھ وقت کے بعد خدائی فضل کے ماتحت یہ
روک دور ہو جائے اور وہ شخص پھر اپنے محبوب مشغلہ میں مصروف ہونے کا موقع پالے.ایسے موقع پر
جو جذ بات اس شخص کے دل میں اٹھیں گے وہی اس دعا میں مخفی ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں کہ ہم اس سفر کی عارضی رخنہ اندازی سے آزاد ہو کر پھر اس کیفیت کی طرف واپس آرہے ہیں کہ جس
میں ہم اپنے خدا کی یاد میں وقت گزار سکیں گے اور اس کی حمد کے گیت گانے کا موقع پائیں گے.ہاں وہی
خدا جو اس سے پہلے بھی متعدد موقعوں پر ہمیں دشمن کے فتنہ سے محفوظ کر کے امن عطا کرتا رہا ہے.یہ جذبہ
کیسا مبارک اور کیسا دلکش اور کیسا پر امن ہے ! مگر افسوس کہ پھر بھی بعض دشمنان اسلام اعتراض سے باز نہیں
آتے اور یہی کہتے چلے جاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اصل غرض جارحانہ
فوج کشی اور دنیا طلبی تھی.ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا
غزوہ بنو لحیان کی تاریخ کے متعلق مؤرخین میں اختلاف ہے.ابن سعد نے اسے ربیع الاول ۶ ھ میں
بیان کیا ہے مگر ابن اسحاق اور طبری نے تصریح کی ہے کہ وہ جمادی الاولی ۶ ھ میں ہوا تھا.میں نے اس جگہ
ابن اسحاق کی پیروی کی ہے.واللہ اعلم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو ریہ کا الزام غزوہ بنولحیان کے ذکر میں ہم نے یہ
بیان کیا ہے کہ پردہ رکھنے کی غرض
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں شمال کی طرف تشریف لے گئے تھے اور بعد میں مدینہ سے کچھ
فاصلہ پر جا کر جنوب کی طرف گھوم گئے.اسی قسم کے واقعات بعض دوسرے غزوات کے متعلق بھی بیان
ہوئے ہیں کہ دشمن سے اپنی حرکات و سکنات کو مخفی رکھنے کی غرض سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا
میں سفر کا مقصد ظاہر نہیں
فرمایا اور مدینہ سے نکلتے ہوئے اصل جہت کو چھوڑ کر دوسری جہت کی طرف تشریف
لے گئے مگر کچھ فاصلہ پر جا کر پھر اصل جہت کی طرف گھوم گئے وغیر ذالک.اس قسم کے واقعات کی بنا پر
جو عربی محاورہ کے مطابق توریة کہلاتے ہیں بعض کو نہ اندیش لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ
افعال چالا کی اور دھو کے میں داخل ہیں جو ایک نبی کی شان سے بعید ہے.اس اعتراض کے جواب میں
یه نام لحیان اور یحیان دونوں طرح آتا ہے.
Page 780
۷۶۵
ہمیں زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں.کیونکہ اس قسم کے اعتراضات زیادہ سمجھ دار طبقہ کی
طرف سے نہیں ہوتے بلکہ عموماً کم علم اور کم فہم لوگوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ گزشتہ
انبیاء اور صلحاء کے حالات سے واقف نہیں بلکہ موقع اور محل کو سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے اور نیک
صرف اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان اول تو دنیا کی کسی بات میں حصہ نہ لے اور اگر کبھی بصورت مجبوری
حصہ لینا پڑے تو اس کے لئے کوئی مادی تدبیر اختیار نہ کرے اور اگر کبھی کوئی تد بیراختیار کرنی پڑے تو
وہ نہایت سادہ اور بھونڈے طریق پر کی جائے اور ہر صورت میں ہر بات برملا ہو اور کبھی کسی بات میں اختفا
اور راز داری کا طریق اختیار نہ کیا جائے.ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اگر نیکی اسی کا نام ہے تو بے شک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض افعال اعتراض کا نشانہ بنتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی نیکی کی
یہی تعریف ہے اور کیا اس تعریف کی رو سے دنیا کا کوئی نبی اور کوئی مصلح ایسا ہے جو ایسے اعتراضوں سے
بچ سکتا ہے؟
دور نہ جاؤ حضرت مسیح ناصری کو ہی لے لو جنہیں اس زمانہ میں یورپ و امریکہ کی ترقی یافتہ اقوام عرش
الوہیت پر بٹھائے ہوئے ہیں اور ہر نیک کام کو ان کے اقوال وافعال کے پیمانے سے ناپتی ہیں مگر کیا یہ
درست نہیں کہ جب ان کے خلاف یہ الزام لگایا گیا کہ وہ حکومت وقت کے خلاف تعلیم دیتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ حکومت کو خراج نہ دو اور اس طرح انہیں حکومت کی نظروں میں معتوب کرنا چاہا تو انہوں نے صاف
اور سیدھا جواب دینے کی بجائے ایک رائج الوقت سکہ منگایا اور اس پر قیصر روما کی تصویر دیکھ کر کہا کہ یہ تو
قیصر کی تصویر ہے.تو پھر جو قیصر کی چیز ہے وہ قیصر کو دو اور جو خدا کی چیز ہے وہ خدا کو دو.اور اس طرح ایک
غیر حقیقی سا جواب دے کر بات کو ٹال دیا.اسی طرح ہندوؤں کی مذہبی کتب میں ذکر آتا ہے کہ شری کرشن
جی مہاراج ( جو ہندوؤں کے سب سے بڑے اوتار گزرے ہیں ) اور ان کے بعض مقدس ساتھی ایک راجہ
کو قتل کرنے کی غرض سے بھیس بدل کر اس کے قلعہ میں داخل ہوئے اور ایک انتقامی غرض کے حصول کے
لئے اپنی اصل شناخت کو چھپایا اور لوگوں کے خیال کو غلط رستے پر ڈال دیا ہے اسی طرح سکھوں کی کتب میں
یہ ذکر آتا ہے کہ جب شاہی فوج نے گورو گوبند جی کا محاصرہ کر لیا جو سکھوں کے ایک نہایت نامور اور ممتاز
گور وگزرے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ہمشکل شخص کو اپنا لباس پہنا کر اسے اپنی جگہ بٹھا دیا اور خود اپنے
: لوقا باب ۲۰ آیت ۱۹ تا ۲۶ و متی باب ۲۲ آیت ۱۵ تا ۲۲ و مرقس باب ۱۲ آیت ۱۳ تا ۱۷
یوگیشور کرشن مصنفہ پنڈت جمو پتی صفحه ۸۶ و ۸۷
Page 781
بعض ساتھیوں کے ساتھ مسلمان حاجیوں کا لباس پہن کر حملہ آوروں کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے
نکل گئے.اگر یہ مذہبی پیشوا با وجود اپنے اس قسم کے افعال کے پاک اور مقدس شمار ہو سکتے ہیں تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بالکل جائز جنگی تدبیر اختیار کرنے کی وجہ سے کس طرح اعتراض ہو سکتا ہے؟
حق یہ ہے کہ اس زمانہ میں اکثر لوگوں کے دلوں میں نیکی اور صداقت کا ایک نہایت ہی غلط مفہوم قائم
ہو گیا ہے حالانکہ حقیقی نیکی یہ نہیں کہ انسان عقل و خرد سے عاری ہوکر بے وقوفی کی حرکات کرے اور خود اپنے
ہاتھوں اپنی تباہی کا بیج بو لے بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان اگر ایک طرف جھوٹ اور غداری سے بچے اور کوئی کام
صداقت اور دیانتداری کے خلاف نہ کرے تو دوسری طرف پوری پوری ہوشیاری کے ساتھ اور ہر پہلو سے
چوکس رہتے ہوئے اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے دینی اور دنیوی ترقیات کے راستے کھولے اگر ایک شخص
ہوشیار اور چوکس ہے مگر جھوٹ اور غداری سے پر ہیز نہیں کرتا اور خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ یقیناً نیک
کہلانے کا مستحق نہیں.اسی طرح اگر ایک شخص صداقت اور وفاداری کو تو اختیار کرتا ہے مگر اپنے کاموں
میں عقل وخرد اور ہوشیاری اور بیدار مغزی نہیں دکھاتا تو اسے بھی ہرگز اعلیٰ درجہ کا نیک نہیں سمجھا
جا سکتا.کیونکہ نیکی کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ہو اور اگر خدا کا تعلق جو ساری
دانائیوں کا سر چشمہ ہے انسان کے اندر عقل و خرد پیدا نہیں کر سکتا تو اور کون سی چیز پیدا کرے گی اور یقیناً اس
صورت میں یہ خدا کا حقیقی تعلق نہیں سمجھا جا سکتا.اسی لئے اسلام نے نیکی کی تعریف میں کسی خاص فعل کو
داخل نہیں کیا بلکہ اصل نیکی دل کے تقویٰ کو قرار دیا ہے اور صرف اُسی فعل کو نیک شمار کیا ہے جو دل کے تقویٰ
کے ساتھ خدا کی رضا اور مخلوق کی بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے حالات پیش آمدہ کے مطابق اختیار کیا
جائے.مثلاً اگر دوستوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا سوال ہو تو اس کے مناسب حال اعلیٰ اخلاق دکھائے
جائیں.دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا سوال ہو تو اس کے مطابق اچھے اخلاق ظاہر کئے جائیں.امن کا
ماحول ہو تو اس کے مطابق بہتر سے بہتر اخلاق کا اظہار کیا جائے اور جنگ کا موقع ہو تو اس کے مناسب
حال اعلیٰ اخلاق دکھائے جائیں.غرض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور مخلوق خدا کی بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے
جو بھی اعلیٰ اور کامل اخلاق دل کے تقویٰ کے ساتھ اختیار کئے جائیں وہی نیکی ہے اور اسلام نے ہر موقع
اور ہر ماحول کے مناسب حال
علیحدہ علیحدہ اخلاق
کی تعین فرما دی ہے اور یہی وہ صحیح تعریف ہے جو نیکی کی
قرار دی جاسکتی ہے اور اسلام کے لئے یہ جائے فخر ہے کہ اس کے مقدس بانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا
ا پنتھ پر کاش مصنفہ گیانی گیان سنگھ صفحہ ۲۰۷
Page 782
میں نیکی کی صحیح تعریف قائم کی ہے اور وہی وہ بزرگ ہستی ہے جس نے ہر میدان میں اعلیٰ ترین اخلاق
کا اظہار کیا ہے اور اعتراض کرنے والے محض جہالت اور کو نہ بینی سے اعتراض کرتے ہیں.جنگ میں اپنی نقل و حرکت کو دشمن سے چھپانا یا کامیاب نتائج پیدا کرنے کے لئے مناسب تدابیر
اختیار کرنا نہ صرف ایک بالکل جائز فعل ہے بلکہ فنون جنگ کے لحاظ سے نہایت ضروری اور واجبی ہے اور
اگر کوئی جرنیل ایسی تدابیر اختیار نہیں کرتا تو وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک تو پھر بھی نہیں کہلا سکتا مگر یقیناً وہ پر لے
درجہ کا بے وقوف جرنیل ضرور سمجھا جائے گا جسے بالکل ابتدائی اور اصولی تدابیر جنگ کا بھی علم نہیں.میں
یقین رکھتا ہوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی تدابیر اختیار نہ فرماتے اور جنگوں میں مخفی رکھنے
والی تدابیر کو کھلے بندوں کرتے تو پھر یہی معترض لوگ آپ پر یہ اعتراض کرتے کہ آپ فنون جنگ سے
بالکل بے بہرہ اور حسن تدبیر کی صفت سے بالکل محروم تھے.یہ ایک قیاس ہی نہیں بلکہ بعض غیر مسلم مؤرخین
نے بعض اسلامی مہموں کی ظاہری ناکامی پر واقعی اس قسم کے اعتراضات کئے ہیں کہ بعض موقعوں
پر مسلمانوں کا ایسی حالت میں دشمن کی قیام گاہ تک پہنچنا کہ وہ ان کی خبر پا کر پہلے سے منتشر ہو چکا ہوتا تھا
اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی مہموں میں سوئے تدبیر سے کام
لیا جاتا تھا.حالانکہ کبھی کسی مہم میں ایسا
ہو جانا سوئے تدبیر کی علامت نہیں بلکہ صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دشمن بھی اپنی جگہ ہوشیار اور چوکس
تھا اور باوجود مسلمانوں کی ہوشیاری اور بیدار مغزی کے وہ کبھی کبھی شرارت کر کے اپنی شرارت کی سزا سے
بچ جاتا تھا.مگر پھر بھی مجموعی نتیجہ بہر حال اسلام کے حق میں پیدا ہورہا تھا.مخالفین اسلام کی یہ ذہنیت اس
بات کے سوا کچھ ثابت نہیں کرتی کہ انہوں نے ہر حال میں اعتراض کا فیصلہ کر رکھا ہے یعنی مسلمان اگر
بیداری مغزی اور حسن تدبیر کا اظہار کریں تو تب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام ہوشیاری اور چالا کی کی
تعلیم دیتا ہے اور اگر وہ کبھی دشمن کی ہوشیاری اور چالا کی کا نشانہ بن جائیں تو تب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ
اسلام میں بیدار مغزی اور حسن تدبیر کا فقدان تھا.اس ذہنیت کا علاج سوائے خدا کے اور کسی کے پاس
نہیں.مگر یہ ایک شکر کی بات ہے کہ اس قسم کے جاہلانہ اعتراض صرف بے وقوف اور ادنی طبقہ کے لوگوں کی
طرف سے کئے جاتے ہیں اور سمجھ دار لوگ اس بات کو جانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ سچا مذ ہب روحانیت کی
ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی عقل کو بھی تیز کرتا ہے اور یہ کہ اسلام کا مقدس بانی صداقت اور دیانت کے
ساتھ ساتھ حسن تدبیر کا بھی مجسمہ تھا.اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ.خلاصہ کلام یہ کہ جنگ میں اپنی حرکات وسکنات کو چھپا کر یا اسی قسم کی اور مناسب احتیاطی تدابیر
Page 783
۷۶۸
اختیار کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کسی نا جائز یا خلاف اخلاق بات کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ حق
یہ ہے کہ یہ تدابیر آپ کی دور اندیشی اور بیدار مغزی کی دلیل ہیں اور جو شخص ان باتوں پر اعتراض کرتا ہے.وہ خود اپنی جہالت کا ثبوت دیتا ہے.یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ توریہ ( یعنی پردہ رکھنا ) اور کذب بیان ( یعنی جھوٹ بولنا) میں زمین آسمان
کا فرق ہے اور کوئی عقل مند ان دونوں کو ایک نہیں قرار دے سکتا.تو ریہ کے معنی چھپانے کے ہیں یعنی ایسے
رنگ میں بات کرنا کہ مصلحت وقت کے ماتحت کسی بات کو پردہ میں رکھا جائے تاکہ فتنہ کی صورت پیدا نہ ہو
لیکن کذب کے معنی خلاف واقعہ بات بیان کرنے اور جھوٹ بولنے کے ہیں اور ان دونوں مفہوموں میں
زمین آسمان کا فرق ہے.ہر شخص اپنی روز مرہ کی زندگی میں سینکڑوں باتوں کو چھپاتا ہے.کوئی شرم وحجاب
کی وجہ سے اور کوئی فتنہ کی روک تھام کی بنا پر اور کسی جائز غرض کے ماتحت.لیکن آج تک کسی عقل مند نے
اس طریق پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اسے ایک بہت اچھا خلق سمجھا جاتا ہے مگر کذب بیانی اور دروغ گوئی
بالکل اور چیز ہے جو ہر شریف انسان کے نزدیک ایک مکروہ اور ناجائز فعل ہے اور اسلام نے تو اسے
نہایت سختی سے روکا اور حرام قرار دیا ہے.حتی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس وقت آپ ایک مجلس
میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے.آپ نے پہلے شرک اور والدین کی نافرمانی کا ذکر فرمایا اور پھر بڑے جوش کے
ساتھ یہ کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے کہ:
الا وَقَوْلَ النُّورِ.اَلا وَقَوْلَ النُّورِ
یعنی ” کان کھول کر سن لو! ہاں پھر کان کھول کر سن لو کہ ان کے بعد سب سے بڑا گناہ
جھوٹ بولنا ہے.راوی کہتا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ اس جوش کے ساتھ بار بار دہرائے کہ ہم نے آپ کی تکلیف کا خیال
کر کے دل میں کہا کہ کاش آپ آب خاموش ہو جائیں اور اس نصیحت کے دہرانے میں اتنی تکلیف نہ اٹھا ئیں.غزوہ بنولحیان کے کچھ عرصہ بعد سریه زید بن حارثه به جانب طرف جمادی الآخرة ۶ ہجری
جمادى الآخرة ۶ ہجری میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی کمان میں پندرہ صحابیوں کا ایک دستہ طرف کی جانب روانہ
بخاری کتاب الشهادات
Page 784
۷۶۹
فرمایا جو مدینہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پر واقع تھا اور اس جگہ ان ایام میں بنو ثعلبہ کے لوگ آباد تھے مگر
قبل اس کے کہ زید بن حارثہ وہاں پہنچتے اس قبیلہ کے لوگ بر وقت خبر پا کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور
زید اور ان کے ساتھی چند دن کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس لوٹ آئے.اس سر یہ میں مسلمانوں کا
جنگی شعار امِتُ اَمِتْ تھا.سریہ زید بطرف جسمی جمادی الآخرة ۶ ہجری اسی ماہ جمادی الآخرۃ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے زید بن حارثہ کو پانچ سومسلمانوں کے ساتھ جسمی
کی طرف روانہ فرمایا جو مدینہ کے شمال کی طرف بنو جذام کا مسکن تھا.اس مہم کی غرض یہ تھی کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام دحیہ کلبی تھا شام کی طرف سے قیصر روم کومل کر واپس آرہے تھے.اور ان کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا جو کچھ تو قیصر کی طرف سے خلعت وغیرہ کی صورت میں تھا.اور کچھ
تجارتی سامان تھا ہے جب دحیہ بنو جذام کے علاقہ کے پاس سے گزرے تو اس قبیلہ کے رئیس ہنید بن عارض
نے اپنے قبیلہ میں سے ایک پارٹی کو اپنے ساتھ لے کر دحیہ پر حملہ کر دیا اور سارا سامان چھین لیا حتی کہ
دحیہ کے جسم پر بھی سوائے پھٹے ہوئے کپڑوں کے کوئی چیز نہیں چھوڑی.جب اس حملہ کا علم قبیلہ بنوضبیب
کو ہوا جو قبیلہ بنوجذام ہی کی ایک شاخ تھے اور ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو چکے تھے تو انہوں نے
بنو جذام کی اس پارٹی کا پیچھا کر کے ان سے لوٹا ہوا سامان واپس چھین لیا اور دحیہ اس سامان کو لے کر مدینہ
میں واپس پہنچے.یہاں آکر دحیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات سے اطلاع دی جس پر
آپ نے زید بن حارثہ کو روانہ فرمایا اور دحیہ کو بھی زید کے ساتھ بھجوا دیا.زید کا دستہ بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ دن کو چھپتا ہوا اور رات کے وقت سفر کرتا ہوا جسمی کی
طرف بڑھا اور عین صبح کے وقت بنو جذام کے لوگوں کو جاد با یا.بنوجذام نے مقابلہ کیا مگر مسلمانوں کے
اچانک حملہ کے سامنے ان کے پاؤں نہ جم سکے اور تھوڑے سے مقابلہ کے بعد وہ بھاگ نکلے اور میدان
مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور زید بن حارثہ بہت سا سامان اور مال مویشی اور ایک سو کے قریب قیدی پکڑ
کر واپس لوٹ آئے.ابن سعد
ه: زرقانی
جبرئیل ان کی شکل میں نظر آئے تھے.۲، ۳: ابن سعد
ابن اسحاق بحوالہ زرقانی حالات سریع علمی
وہی دحیہ کلبی ہیں جن کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے
Page 785
۷۷٠
مگرا بھی زید مدینہ میں پہنچ نہیں تھے کہ قبیلہ بنوضیب کے لوگوں کو جو قبیلہ بنو جذام کی شاخ تھے زید کی
اس مہم کی خبر پہنچ گئی اور وہ اپنے رئیس رفاعہ بن زید کی معیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ! ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہماری بقیہ قوم کے لئے امن کی تحریر ہو چکی ہے
تو پھر ہمارے قبیلہ کو اس حملہ میں کیوں شامل کیا گیا ہے.آپ نے فرمایا ہاں یہ درست ہے مگر زید کو اس کا
علم نہیں تھا اور پھر جو لوگ اس موقع پر مارے گئے تھے ان کے متعلق آپ نے بار بارافسوس کا اظہار کیا.اس پر رفاعہ کے ساتھی ابوزید نے کہا یا رسول اللہ ! جولوگ مارے گئے ہیں ان کے متعلق ہمارا کوئی مطالبہ
نہیں یہ ایک غلط فہمی کا حادثہ تھا جو ہو گیا.مگر جو لوگ زندہ ہیں اور جو ساز وسامان زید نے ہمارے قبیلہ
سے پکڑا ہے وہ ہمیں واپس مل جانا چاہئے.آپ نے فرمایا ہاں یہ بالکل درست ہے اور آپ نے
فوراً حضرت علی کو زید کی طرف روانہ فرمایا اور بطور نشانی کے انہیں اپنی تلوار عنایت فرمائی اور زید کو کہلا
بھیجا کہ اس قبیلہ کے جو قیدی اور اموال پکڑے گئے ہیں وہ چھوڑ دئے جائیں.زید نے یہ حکم پاتے ہی فوراً
سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور غنیمت کا مال بھی واپس لوٹا دیا یا
اس سریہ کی تاریخ کے متعلق ایک اشکال ہے جس کا ذکر ضروری ہے.ابن سعد اور اس کی اتباع میں
دیگر اہل سیر نے اس سریہ کی تاریخ جمادی الآخرۃ 1 ہجری لکھی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے مگر علامہ ابن قیم
نے زاد المعاد میں تصریح کی ہے کہ یہ سریہ ۷ ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تھا.اور غالباً ابن قیم کے
قول کی بنیاد یہ ہے کہ اس سریہ کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دحیہ کلبی قیصر سے مل کر مدینہ کو واپس آرہے تھے
کہ انہیں راستہ میں بنو جذام نے لوٹ لیا اور یہ مسلّم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کو قیصر کی
طرف خط دے کر صلح حدیبیہ کے بعد بھجوایا تھا اس لئے یہ واقعہ کسی صورت میں حدیبیہ سے پہلے نہیں
ہوسکتا.یہ دلیل اپنی ذات میں بالکل صاف اور واضح ہے اور اس کی روشنی میں ابن سعد کی روایت یقیناً
قابل رد قرار پاتی ہے مگر خاکسار کی رائے میں ایک تو جید ایسی ہے جسے علامہ ابن قیم نے نظر انداز کر دیا ہے
اور وہ یہ کہ ممکن ہے کہ قیصر کی ملاقات کے لئے دحیہ شام میں دو دفعہ گئے ہوں.یعنی پہلی دفعہ وہ صلح حدیبیہ
سے قبل از خود تجارتی غرض کے لئے گئے ہوں اور قیصر سے بھی ملے ہوں اور دوسری دفعہ صلح حدیبیہ کے بعد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیصر کی طرف
ابن سعد وزرقانی
یہ نام رحیہ اور رحیہ دونوں طرح آتا ہے
زادالمعاد مصنفہ ابن قیم جلد ا صفحه ۳۸۰
Page 786
221
پیغامبر بننے کے لئے اس غرض سے چنا ہو کہ وہ پہلے قیصر سے مل چکے ہیں.اس توجیہ کی تائید اس طرح بھی
ہوتی ہے کہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس سفر میں دحیہ کے پاس تجارتی سامان تھا اور صلح حدیبیہ کے بعد
والے سفر میں بظاہر تجارتی سامان کا تعلق نظر نہیں آتا.یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دحیہ کا یہ سفر محض تجارتی غرض
سے ہو اور ابن سعد کے راوی نے اس کے دوسرے سفر کے ساتھ اس سفر کو خلط کر کے قیصر کی ملاقات اور
خلعت کے ذکر کو قیا سا شامل کر لیا ہو.واللہ اعلم
سریہ زید بن حارثہ بطرف وادی القری رجب ۶ ہجری سریہ جسمی کے قریباً ایک ماہ بعد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر زید بن حارثہ کو وادی القریٰ کی طرف روانہ فرمایا.جب زید کا دستہ وادی القریٰ میں پہنچا تو بنو فزارہ
کے لوگ ان کے مقابلہ کے لئے تیار تھے.چنانچہ اس معرکہ میں متعد د مسلمان شہید ہوئے اور خود زید کو
بھی سخت زخم آئے مگر خدا نے اپنے فضل سے بچا لیا.کے
وادی القریٰ جس کا اس سریہ میں ذکر ہوا ہے وہ مدینہ سے شمال کی طرف شامی راستہ پر ایک آباد وادی
تھی جس میں بہت سی بستیاں آباد تھیں اور اسی واسطے اس کا نام وادی القریٰ پڑ گیا تھا یعنی بستیوں والی
وادی اور ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس وادی میں بعض یہودی قبائل بھی آباد تھے جو خیبر کے بعد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مفتوح ہوئے.زید بن حارثہ کی امارت پر لوگوں کا اعتراض گزشتہ چار پانچ مہوں میں زید بن حارثہ کی
کمان کا ذکر آیا ہے.ہمارے ناظرین جانتے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہیں کہ زید ایک آزاد کردہ غلام تھے اور قرآنی حکم
کے نزول سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور ان کی وفات تک جو ۸ ہجری
میں غزوہ موتہ میں ہوئی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعدد مہموں کا امیر مقررفرمایا اور بڑے بڑے
صحابہ کو ان کی ماتحتی میں رکھا.ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اسامہ سے بھی آپ کو خاص محبت تھی.چنانچہ اکثر صحابہ کو خیال تھا کہ اسامہ جس بے تکلفی اور آزادی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات
کر لیتے ہیں وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں.اسامہ کو بھی آپ نے متعد دمہموں میں امیر مقرر فرمایا اور بعض
بڑے بڑے صحابہ کو ان کی ماتحتی میں رکھا اور جب اس پر بعض نو آموز مسلمانوں نے اسامہ کے نسب کی وجہ
ابن سعد
: ابن اسحاق
زرقانی
Page 787
۷۷۲
سے اعتراض کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا تم اسامہ سے پہلے زید کی امارت پر بھی اعتراض
کر چکے ہو مگر اسلام میں صرف ذاتی اہلیت دیکھی جاتی ہے.اور خدا کی قسم جس طرح زید امارت کا اہل تھا
اسی طرح اس کا بیٹا اسامہ بھی امارت کا اہل ہے اور مجھے یہ دونوں نہایت درجہ محبوب ہیں.اس ارشاد نبوی
پر جو اسلام کی حقیقی مساوات کا حامل تھا صحابہ کی گردنیں جھک گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام میں کسی
س کا غلام یا غلام زادہ ہونا یا بظاہرکسی ادنیٰ طبقہ سے تعلق رکھنا اس کی ترقی کے رستہ میں حارج نہیں
ہوسکتا اور اصل معیار بہر صورت تقویٰ اللہ اور ذاتی قابلیت پر مبنی ہے.بخاری ابواب مناقب و طبقات ابن سعد حالات زید واسامه
Page 788
۷۷۳
مساوات اسلامی پر ایک مختصر نوٹ
اس جگہ ایک مختصر سانوٹ اسلامی مساوات کے متعلق سپرد قلم کرنا بے موقع نہ ہوگا.کیونکہ یہ مسئلہ ایسا
ہے کہ جس کے متعلق اکثر لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے.یعنی جہاں ایک طبقہ نے اسلامی مساوات کے
یہ معنی سمجھ رکھے ہیں کہ اسلام میں سب چھوٹے بڑے ہر جہت سے برابر ہیں اور اسلام کسی صورت میں کسی
شخص کے امتیاز یا بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا اور تمام امتیازات کو مٹا کر ہر شخص کو ہر لحاظ سے ایک لیول پر کھڑا کرنا
چاہتا ہے وہاں ایک دوسرے طبقہ نے اسلام میں بھی اسی رنگ کے ناگوار طبقے بنارکھے ہیں جو اکثر دوسری
قوموں میں پائے جاتے ہیں اور ان طبقات کے علیحدہ علیحدہ حقوق قرار دے دئے گئے ہیں.بلکہ ان
طبقات کے اندر کی خلیج کو وسیع تر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.سو جانا چاہئے کہ صحیح اسلامی تعلیم کی رو سے یہ
دونوں خیالات افراط و تفریط کے طریق پر غلط اور نا درست ہیں بلکہ اصل اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جہاں تک
حقوق اور ذرائع ترقی کے حصول کا سوال ہے سب لوگ برابر ہیں اور کسی فرد یا کسی جماعت کو کسی دوسرے
فرد یا کسی دوسری جماعت پر کسی رنگ میں فضیلت حاصل نہیں اور اس جہت سے اسلام میں قطعاً کوئی درجے
یا طبقے پائے نہیں جاتے بلکہ پوری پوری مساوات ہے لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص کسی جائز وجہ سے کوئی
دینی یا دنیوی ترقی اور بڑائی حاصل کر لیتا ہے تو حقوق کے معاملہ کو الگ رکھتے ہوئے جس میں بہر حال
سب برابر ہیں اسلام عام تعلقات میں ایسے شخص کی حاصل شدہ بڑائی اور ترقی کو تسلیم کرتا ہے اور اسے
اس کے جائز مرتبہ سے گرا کر ظلم اور حق تلفی کے طریق کو اختیار نہیں کرتا.خلاصہ یہ کہ جہاں ایک طرف
اسلام نے سب بنی نوع آدم کو حقوق اور ذرائع ترقی کے حصول کے معاملہ میں ایک لیول یعنی ایک سطح
پر کھڑا کیا ہے اور کسی نا واجب نسلی اور قومی یا خاندانی یا انفرادی امتیاز کو تسلیم نہیں کیا وہاں افراد اور قوموں کی
حاصل شدہ بڑائی اور ترقی کو جبر و تشدد کے رنگ میں مٹایا بھی نہیں اور انہیں ان کی محنت یا خوش بختی کے ثمرہ
سے محروم نہیں کیا البتہ اس صورت میں گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے کے لئے مؤثر تدابیر ضرور اختیار کی
ہیں اور یہی وہ اعلیٰ اور وسطی طریق ہے جسے نظر انداز کر کے دنیا آج کل مختلف قسم کے فتنوں کا شکار بن رہی
Page 789
۷۷۴
ہے اور اس زمانہ کی سرمایہ داری اور اشتراکیت انہی فتنوں سے پیدا شدہ انتہا ئیں ہیں جن میں سے ایک
میں افراط کی صورت پیدا ہوگئی ہے اور دوسری میں تفریط کی.اسلامی مساوات کا اصولی نظریہ اسلامی مساوات کے فلسفہ کا نچوڑ اور خلاصہ چند قرآنی آیات
اور چند احادیث نبوی میں آجاتا ہے.قرآن شریف میں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
يَايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ
یعنی ”اے لوگو! تم آپس کے معاملات میں خدا کا تقویٰ اختیار کیا کرو اور اسی سے ڈرتے
رہو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس ایک جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا
اور پھر اس جوڑے سے اس نے دنیا میں کثیر التعداد مرد اور عورت پھیلا دئے.“
اس قرآنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس ابدی حقیقت کی طرف توجہ دلا کر کہ وہ سب
ایک ہی باپ کی اولا دا ور ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں دنیا میں صحیح مساوات
کی بنیا د قائم کر دی ہے اور
اس اصول کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خواہ بعد کے حالات کے نتیجے میں مختلف انسانوں اور مختلف قوموں
اور مختلف طبقات میں کتنا ہی فرق پیدا ہو جائے انہیں آپس کے معاملات میں اس بات کو کبھی نظر انداز نہیں
کرنا چاہئے کہ بہر حال اپنی اصل کے لحاظ سے وہ ایک ہی باپ کی نسل ہیں.کیا اگر ایک باپ کے بیٹوں
میں سے بعض بچے دوسروں کی نسبت زیادہ دولت یا زیادہ طاقت یا زیادہ اثر ورسوخ حاصل کر لیں اور دوسرے
ان باتوں میں نسبتاً پس ماندہ رہیں تو وہ اس فرق کی وجہ سے بھائی بھائی نہیں رہتے اور کوئی غیر چیز
بن جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہر گز نہیں.دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمُ مِّنْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ
يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ...يَا يُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَيْرٌ
یعنی سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں سوائے مسلمانو! ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ
: سورة النساء:۲
۲ ، ۳ : سورة الحجرات : ۱۲:۱۱ ۴ : سورة الحجرات :۱۴
Page 790
۷۷۵
تم میں سے ایک فریق دوسرے فریق پر ہنسی اڑائے اور اسے ذلیل خیال کرے کیونکہ (جب
سب لوگ اپنی اصل کے لحاظ سے برابر ہیں اور سب کے لئے ترقی کے رستے یکساں کھلے ہیں
تو ہو سکتا ہے کہ وہ فریق جس پر تم آج ہنسی اڑاتے ہو کل کو تم سے آگے نکل جائے یا ہو سکتا ہے
کہ وہ اب بھی اپنے بعض اوصاف حمیدہ کے لحاظ سے تم سے بہتر ہو...اے لوگو! اچھی طرح
سن لو کہ ہم نے تم سب کو مرد و عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور بے شک ہم نے تم میں
قوموں اور قبیلوں کی تقسیم قائم کی ہے مگر یاد رکھو کہ یہ تقسیم اس غرض سے ہرگز نہیں کہ تم ایک
دوسرے کے مقابل پر تفاخر اور بڑائی سے کام لو بلکہ یہ تقسیم صرف اس غرض سے ہے کہ تمہارے
درمیان آپس میں شناخت اور تعارف کا ذریعہ قائم رہے ورنہ خدا کے نزدیک تم میں سے بڑا اور
معزز وہی ہے جو ذاتی طور پر زیادہ اوصاف حمیدہ کا مالک اور زیادہ متقی اور زیادہ پر ہیز گار ہے.اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو وہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے بڑی دوراندیشی اور بڑی حکمت پر
مبنی ہے کیونکہ وہ علیم وخبیر خدا ہے.“
اسی طرح حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :
يأَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ.اَلأَلَا فَضْلَ لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي
وَلَا لِعَجَمِيّ عَلى عَرَبِيّ.وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى اَسْوَدَ وَلَا لَاسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوىٰ.اَبَلَّغْتُ؟ قَالُوا قَدْ بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
یعنی جو خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع کے موقع پر حج کے درمیانی دن میں
منی کے مقام میں دیا اس میں آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ”اے لوگو! تمہارا رب ایک
ہے اور تمہارا باپ بھی ایک تھا.پس ہوشیار ہو کر سن لو کہ عربوں کو عجمیوں پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ
عجمیوں کو عربوں پر کوئی فضیلت ہے.اسی طرح سرخ وسفید رنگ والے لوگوں کو کالے رنگ والے
لوگوں پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ کالے لوگوں کو گوروں پر کوئی فضیلت ہے.ہاں جو بھی ان میں
سے اپنی ذاتی نیکی سے آگے نکل جائے وہی افضل ہے.لوگو! بتاؤ کیا میں نے تمہیں خدا کا پیغام
پہنچا دیا ہے؟ سب نے عرض کیا.بے شک خدا کے رسول نے اپنی رسالت پہنچادی ہے.“
پھر فرماتے ہیں:
ل : مسند احمد بن حنبل
Page 791
قَدْ اَذْهَبَ اللهُ عَنْكُمُ عُمِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخُرَهَا بِالْآبَاءِ - إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنْ تَقِيٌّ وَفَاجِ
شَقِيٌّ وَالنَّاسُ بَنُو ادَمَ وَادَمَ مِنْ تُرَابٍ
یعنی ”اے مسلمانو! خدا تعالیٰ نے ایمان کے ذریعہ تم میں سے زمانہ جاہلیت کے بیجا
کبر و غرور اور آبا و اجداد کی وجہ سے بے جا تفاخر کرنے کی مرض کو دور کر دیا ہے کیونکہ اسلامی
پیمانہ صرف یہ ہے کہ ایک شخص خدا کو ماننے والا اور نیک عمل بجالانے والا ہوتا ہے اور دوسرا
بد عمل ہوتا ہے اور اچھے اوصاف سے محروم اور یاد رکھو کہ سب لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم
مٹی سے پیدا ہوا تھا.“
پھر فرماتے ہیں:
النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا -
یعنی دنیا میں لوگ بھی معدنیات کی طرح ہیں.جو ایک ہی قسم کے عناصر ہوتے ہوئے
اور ایک ہی قسم کی مٹی کے نیچے دبے ہوئے آہستہ آہستہ مختلف رنگ اور مختلف اوصاف اختیار
کر لیتے ہیں.مگر سن لو کہ ترقی اور بڑائی کی جو معروف علامتیں اسلام سے پہلے سمجھی جاتی
تھیں.( یعنی عقل و دانش، سخاوت و شجاعت، طاقت واثر وغیرہ ) وہی اب بھی قائم ہیں اور جو
لوگ ان اوصاف کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں بڑے سمجھے جاتے تھے وہ اب اسلام میں بھی
بڑے سمجھے جائیں گے ( کیونکہ اسلام کسی شخص کی حاصل شدہ بڑائی کو چھینتا نہیں ) مگر شرط یہ
ہے کہ وہ علم دین اور ذاتی نیکی اختیار کر لیں.“
اوپر کے حوالوں سے جو اسلامی مساوات کے نظریہ کے متعلق اصولی رنگ رکھتے ہیں.مندرجہ ذیل
باتیں ثابت ہوتی ہیں:
-1
-۲
یہ کہ اپنی اصل کے لحاظ سے سب لوگ ایک باپ کی نسل اور ایک درخت کی شاخیں ہیں اور کسی فرد
کو دوسرے فرد پر اور کسی قوم کو دوسری قوم پر محض نسلی فرق کی بنا پر کوئی امتیاز حاصل نہیں.یہ کہ مسلمان ایک نبی کی امت اور ایک ایمان کے حامل ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں.یہ کہ زمین کے اندر کی معدنیات کی طرح مختلف قومیں اور مختلف افراد ایک دوسرے سے مختلف
اوصاف اختیار کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں مگر ان کی وجہ سے کسی فرد کو دوسرے فرد پر اور کسی قوم
ترمذی ابواب المناقب
: بخاری ابواب المناقب
Page 792
222
کو دوسری قوم پر بڑائی اور فخر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے.یہ کہ اسلام سے قبل جو اوصاف حمیدہ قومی یا انفرادی بڑائی کی بنیا د سمجھے جاتے تھے مثلاً
عقل و دانش، سخاوت و شجاعت، طاقت واثر وغیرہ وہ اسلام میں بھی بدستور قائم ہیں.مگر اسلام
نے ان پر اس شرط کا اضافہ کر دیا ہے کہ عام معروف اوصاف کے علاوہ دینداری کا وصف پایا جانا
بھی ضروری ہے.یہ کہ اسلام نے سب سے بڑا وصف دینداری اور تقوی اللہ کو قرار دیا ہے کیونکہ یہ وصف
خدائے اسلام کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور جو شخص اس وصف میں ممتاز ہوگا وہی دوسروں پر
ممتاز سمجھا جائے گا.عام تعلقات میں مراتب کو ملحوظ رکھنے کی تلقین اسلامی مساوات کے متعلق یہ بنیادی نظریہ
بیان کرنے کے بعد اسلام اس سوال کو لیتا
ہے کہ جب اصل کے لحاظ سے ایک ہونے کے باوجود مختلف لوگوں کے حالات اور اوصاف مختلف ہو سکتے
ہیں تو اس ناگزیر اختلاف کی موجودگی میں مختلف مدارج کے لوگوں کے متعلق عام تمدنی معاملات میں کیا
رویہ ہونا چاہئے.سو اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ
یعنی ”اے مسلمانو! تمہارے لئے ضروری ہے کہ آپس کے معاملات میں لوگوں کے معروف
مرتبوں کا خیال رکھا کرو اور ان کے حالات اور درجہ کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو.“
اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ جو لوگ کسی دینی یا دنیوی بنا پر کوئی رتبہ یا بڑائی حاصل کر لیں تو عام
معاملات میں ان کے مرتبہ کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ واجبی احترام سے پیش آنا اسلامی اخلاق کا حصہ
ہے.مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بات ہے کہ جب یہودی قبیلہ بنوقریظہ کے فیصلہ کے لئے
سعد بن معاذ انصاری قبیلہ اوس کے رئیس موقع پر تشریف لے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
آتا دیکھ کر صحابہ سے فرمایا:
قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ -
یعنی اپنے ریس کے اکرام اور احترام کے لئے کھڑے ہو جاؤ“
لے ابوداؤد کتاب الادب
ے : بخاری ابواب المناقب
Page 793
227
اسی طرح قرآن شریف سے پتہ لگتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت موسی کو پیغام رسالت دے
کر فرعون کی طرف بھیجا تو حضرت موسی کو تاکید فرمائی کہ (چونکہ فرعون کو اس وقت ملک میں رتبہ حاصل
ہے اس لئے ) اس کے ساتھ نرمی اور ادب کے طریق پر بات کرنا ہے
عدالتی امور میں مکمل مساوات لیکن اس کے مقابل پر عدالتی اور قضائی حقوق کے متعلق
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کن شاندار الفاظ
میں فرماتے ہیں کہ :
إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ.وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْاَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعُتُ يَدَهَا
یعنی " تم سے پہلے اس بات نے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا کہ جب ان میں سے کوئی
چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اسے سزا دیتے تھے اور جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اسے
چھوڑ دیتے تھے.سوا چھی طرح کان کھول کر سن لو کہ مجھے اس پاک ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ
میں میری جان ہے کہ اگر میری لڑکی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اسلامی طریق پر اس کے
بھی ہاتھ کاٹوں گا.“
اللہ ! اللہ ! کیسے زور دار الفاظ ہیں اور کس جلال کے ساتھ اسلامی مساوات کو قائم کیا گیا ہے! اور یہ
تعلیم وہ تھی جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے بھی بڑی سختی کے ساتھ مد نظر رکھا.چنانچہ حضرت
ابوبکرخلیفہ اول رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے سب سے پہلے خطبہ میں فرماتے ہیں :
الضَّعِيفُ فِيْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِى حَتَّى اَرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ فِيُكُمُ ضَعِيفٌ
عِنْدِي حَتَّى أَخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ _
یعنی ”اے مسلمانو! سن لو کہ تم میں سے کمزور ترین شخص میرے لئے اس وقت تک قوی ہوگا
جب تک کہ میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں اور تم میں سے قوی ترین شخص میرے لئے اس وقت تک
کمزور ہو گا جب تک کہ میں اس سے وہ حق جو اس نے کسی اور کا دبایا ہوا ہو واپس نہ لے لوں.“
اسی طرح حضرت عمر خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ شمالی عرب کے ایک
: سورة طه : ۴۵
ابن ہشام امرسقیفہ بنی ساعدہ
بخاری کتاب الحدود
Page 794
229
بڑے رئیس جبلہ بن ایم نامی نے جو مسلمان ہو چکا تھا کسی غریب مسلمان
کو غصہ میں آکر تھپڑ مار دیا.جب
حضرت عمر کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے جبلہ کو بلا کر فر مایا.جبلہ! میں سنتا ہوں کہ تم نے ایک غریب
مسلمان
کو تھپڑ مارا ہے.اگر تم نے ایسی حرکت کی ہے تو خدا کی قسم تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا.‘اس پر جبلہ
جس میں غالباً ابھی تک جاہلیت والے تکبر کی رگ باقی تھی مغرور ہوکر مرتد ہو گیا.ملکی عہدوں کی تقسیم میں مکمل مساوات عدالتی حقوق کے سوال کے بعد عہدوں اور
ذمہ داریوں کی تقسیم کا سوال آتا ہے اور ایک لحاظ سے
یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے سو اس کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے:
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
یعنی ”اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ قومی اور ملکی عہدوں
کی تقسیم کے معاملہ میں
جو خدا کے نزدیک ایک مقدس امانت کا رنگ رکھتے ہیں صرف ذاتی قابلیت اور ذاتی اہلیت
کو دیکھا کرو اور جو شخص بھی اپنے ذاتی اوصاف کے لحاظ سے کسی عہدہ کا اہل ہوا سے وہ عہدہ
سپر دکیا کرو خواہ وہ کوئی ہو اور پھر اے مسلمانو! جب تم کسی عہدہ یا ذمہ داری کے کام پر مقرر کئے جاؤ
تو تمہارا فرض ہے کہ لوگوں میں کامل عدل وانصاف کا معاملہ کرو.“
یہ زریں تعلیم ہمیشہ اسلامی حکومتوں کا طرہ امتیاز رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں بعض
بظاہر ادنیٰ سے ادنیٰ لوگ ترقی کر کے عروج کے کمال تک پہنچے ہیں چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جو ایک آزاد شدہ غلام تھے کئی فوجی دستوں کا امیر مقررفرمایا
اور پھر زید کی وفات کے بعد آپ نے ان کے نوجوان فرزند اسامہ بن زید کو بھی ایک بڑی فوج کا امیر
مقرر فرمایا جس میں بعض بڑے بڑے صحابہ شامل تھے جو قدیم دستور کے مطابق گویا عرب سوسائٹی میں
پہاڑ کی طرح سمجھے جاتے تھے اور جب اس پر بعض نا سمجھ نو مسلموں میں چہ میگوئی ہوئی کہ ایک نو جوان
غلام زادہ کو ایسے ایسے معمر اور جلیل القدر لوگوں پر امیر مقرر کیا گیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہایت غصہ کے ساتھ فرمایا کہ:
إِنْ تَطْعِنُوا فِى أَمَارَتِهِ فَقَدْ كُنتُمْ تَطْعِنُونَ فِي آمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ
فتوح البلدان حالات جنگ یرموک
: سورة النساء : ۵۹
Page 795
ZA+
لَخَلِيقَالِلَامَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ اَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ
یعنی ” تم اسامہ کی امارت پر
نکتہ چینی کرتے ہو اور اس سے قبل تم اس کے باپ زید پر بھی
نکتہ چینی کر چکے ہو.خدا کی قسم جس طرح اس کا باپ امارت کا اہل تھا اور مجھے بہت محبوب تھا اسی
طرح اس کے بعد اسامہ بھی امارت کا اہل ہے اور مجھے بہت محبوب ہے.“
میه اسی مبارک تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلام میں ہمیشہ بظاہر ادنی ترین لوگوں نے اعلیٰ سے
اعلیٰ ترقی حاصل
کی اور کبھی کسی شخص کی غربت یا نسلی پستی اس کی ترقی میں روک نہیں بنی.چنانچہ اس کی مزید مثالیں دیکھنی
ہوں تو اس کتاب کے حصہ دوم کا وہ باب ملاحظہ کیا جائے جو غلامی کی بحث سے تعلق رکھتا ہے.سوشل اجتماعوں میں برادرانہ اختلاط اس جگہ یہ سوال ہوسکتا ہے کہ عہدوں اور ذمہ داری کے
کاموں کے متعلق تو بے شک اسلام نے حقیقی مساوات کی
تعلیم دی ہے اور سب کے لئے ترقی کا ایک جیسا رستہ کھول دیا ہے مگر ہوسکتا ہے کہ اس انتظامی مساوات
کے باوجود تمدنی معاملات اور آپس کے میل ملاقات کے بارے میں مختلف قسم کے لوگوں میں خلیج باقی رہے
اور اسلام نے اس خلیج کو دور نہ کیا ہو.سو اس کے جواب میں یا درکھنا چاہئے کہ اسلام نے اس رخنہ کو بھی
بڑی سختی کے ساتھ بند کیا ہے.چنانچہ اس قرآنی ارشاد کے علاوہ جو اوپر گزر چکا ہے کہ سب مسلمان آپس
میں بھائی بھائی ہیں اور انہیں بھائیوں کی طرح مل کر رہنا چاہئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمدنی تعلقات
کے سب سے بڑے ذریعہ اور سب سے بڑے میدان یعنی آپس کی دعوتوں اور کھانے پینے کی ملاقاتوں
وغیرہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ :
شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ _
یعنی سب سے بری اور سب سے زیادہ قابل نفرت دعوت وہ دعوت ہے جس میں
صرف امیر بلائے جائیں اور غریبوں کو نہ بلایا جائے اور جو شخص کسی بھائی کی دعوت کا انکار کرتا
ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نا فرمان ہے.“
اس مبارک ارشاد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت نا پسند فرمایا ہے کہ امیر لوگ اپنی
دعوتوں وغیرہ میں صرف امیروں کو مدعو کریں اور غریبوں کو گویا کوئی اور جنس خیال کرتے ہوئے بھول
بخاری ابواب مناقب
: سورة الحجرات : 11
: بخاری کتاب النکاح
Page 796
ZMI
جائیں اور دراصل مساوات کی روح زیادہ تر تمدنی معاملات میں ہی بگڑنی شروع ہوتی ہے.کیونکہ اس قسم
کے تمدنی معاملات کا اثر براہ راست دل پر پڑتا ہے.اسی طرح آپ نے یہ تاکید بھی فرمائی ہے کہ اگر کوئی
غریب کسی امیر کی دعوت کرے تو امیر کے لئے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اپنی امارت کے گھمنڈ میں آکر یا یہ
خیال کر کے کہ غریب کے ہاں کا کھانا اس کی عادت اور مزاج کے مطابق نہیں ہوگا غریب کی دعوت قبول
کرنے سے انکار کر دے.چنانچہ اس قسم کی دعوتوں کا رستہ کھولنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں:
لَوُ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ لَا جَبْتُ
یعنی اگر کوئی غریب شخص کسی بکری یا بھیڑ کا ایک پایہ پکا کر بھی مجھے دعوت میں بلائے تو
میں اس کی دعوت کو ضرور قبول کروں گا.“
یا در ہے کہ اس جگہ کواع کے معنی پائے کے نچلے حصہ کے ہیں جو نوں سے نیچے ہوتا ہے اور یقینا وہ
ایک ادنی قسم کی غذا ہے کیونکہ ٹخنوں کے نیچے کا حصہ قریباً گھر ہی بن جاتا ہے ،لیکن اگر مراع کے معنی
پورے پائے کے بھی سمجھے جائیں تو پھر بھی عربوں کی روایات سے یہ ثابت ہے کہ قدیم زمانہ میں عرب
لوگ پائے کو اچھی غذا نہیں سمجھتے تھے چنانچہ عربوں میں مشہور محاورہ تھا کہ:
لا تُطْعِمِ الْعَبْدَ الْكُرَاعَ فَيَطْمَعُ فِي النَّدَاعِ -
یعنی ” اپنے غلام کو پایہ بھی کھانے کو نہ دوور نہ وہ اس سے اوپر نظر اٹھا کر دست و ران کے
گوشت کی بھی طمع کرنے لگے گا.“
بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنا ذاتی اسوہ پیش کر کے مسلمانوں کو تحریک
فرمائی ہے کہ خواہ دعوت کرنے والا کتنا ہی غریب ہو اس کی دعوت کو غربت کی وجہ سے رد نہ کرو ورنہ یا درکھو
کہ تمہاری سوسائٹی میں ایسار خنہ پیدا ہو جائے گا جو آہستہ آہستہ سب کو تباہ کر کے رکھ دے گا.مجلسوں میں مل کر بیٹھنے کے متعلق بھی اسلام یہی سنہری تعلیم دیتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہئے کہ اگر کوئی
بڑا شخص بعد میں آئے تو کسی چھوٹے شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ اسے دے دی جائے.چنانچہ حدیث میں
آتا ہے:
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيُجْلَسُ فِيهِ آخَرُ
بخاری کتاب النکاح
: اقرب الموارو
: تاج العروس
Page 797
۷۸۲
وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرماتے تھے کہ کوئی شخص اپنی جگہ
سے اس لئے اٹھایا جائے کہ تا اس کی جگہ کوئی دوسرا شخص بیٹھ جائے.اور فرمایا کرتے تھے کہ
اگر جگہ تنگ ہو اور زیادہ آدمی آجا ئیں تو پھر سب سمٹ سمٹ کر آنے والوں کے لئے گنجائش
نکال لیا کرو.“
یہی اصول نمازوں کے موقع پر مسجدوں میں ملحوظ رکھا گیا ہے جہاں کسی شخص کے لئے کوئی جگہ ریز رو
نہیں ہوتی.اگر ایک خادم پہلے آتا ہے تو وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا اور اگر ایک آقا پیچھے پہنچتا ہے تو وہ
آخری صف میں بیٹھے گا.غرض خدا کے گھر میں امیر وغریب ، خادم وآقا، حاکم و محکوم ، طاقتور اور کمز ورسب
برابر ہوتے ہیں اور کوئی امتیاز ملحوظ نہیں رکھا جاتا.یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تھا جس میں
آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح مل جل کر بیٹھتے تھے کہ بعض اوقات ایک اجنبی شخص کے لئے آپ کی
مجلس میں اس بات کا جانا اور پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں.خادم و آقا کے تعلقات خادم و آقا کے تعلقات کا سوال بھی ایک بہت اہم سوال ہے مگر چونکہ
اس سوال کے متعلق کتاب ہذا کے حصہ دوم میں مسئلہ غلامی کی ذیل
میں اصولی بحث گزر چکی ہے اس لئے اس جگہ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں.صرف اس قدرا شارہ کافی ہے
کہ خادموں اور غلاموں کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے بھی اسلام نے نہایت تاکیدی ہدا یتیں دی ہیں
مثلاً آقاؤں کو ہوشیار کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصولی رنگ میں فرماتے ہیں :
لک
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِه
یعنی ” تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی جہت سے بعض دوسرے لوگوں کا آقا اور افسر ہوتا
ہے پس ہر شخص کو ہوشیار رہنا چاہئے کیونکہ اسے اس کے سب ماتحت لوگوں کے متعلق
پوچھا جائے گا.“
اور خادموں اور آقاؤں کی درمیانی خلیج کو اڑانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ :
اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ اَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوُهُ تَحْتَ يَدِهِ
بخاری کتاب الادب
صحیح مسلم کتاب الامارة نیز مسند احمد جلد ثانی صفحه ۵۵
بخاری ابواب الحجرت
Page 798
۷۸۳
فَلْيُطْعِمُهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا
يَغْلِبُهُمْ فَاعِيُنُوهُمْ
یعنی ” تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں.پس جب کسی شخص کے ماتحت اس کا کوئی بھائی
ہو تو اسے چاہئے کہ اپنے خادم بھائی کو اس کھانے میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے جو وہ خود کھاتا
ہے اور اس لباس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے جو وہ خود پہنتا ہے اور اے مسلمانو! تم اپنے
خادموں کو کوئی ایسا کام نہ دیا کرو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو اور اگر کبھی مجبوراً انہیں کوئی
ایسا کام دینا پڑے تو پھر اس کام میں خود بھی ان کی مدد کیا کرو.“
یہ حدیث جیسا کہ اس کے الفاظ اور اسلوب بیان سے ظاہر ہے ایک نہایت اہم اور اصولی حدیث ہے
اور ان کی مدد کیا کرو“ کے الفاظ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ کام ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ اگر وہ خود آقا کو کرنا
پڑے تو وہ اسے اپنے لئے موجب عار سمجھے بلکہ ایسا ہونا چاہئے کہ جسے خود آقا بھی کر سکتا ہو اور کرنے کو
تیار ہو.گویا اس حدیث میں خادموں کے ساتھ حسن سلوک اور برادرانہ برتاؤ کی تلقین کے علاوہ یہ تعلیم
بھی دی گئی ہے کہ کسی مسلمان کے لئے زیبا نہیں کہ وہ کسی کام کو اپنے لئے موجب عار سمجھے یا یہ خیال کرے
کہ یہ کام صرف خادم کے کرنے کا ہے میرے کرنے کا نہیں.چنانچہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کا کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے اور کسی کام کو عار نہیں سمجھتے تھے.ہے
یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ اوپر کی حدیث میں جو خول کا لفظ آیا ہے وہ عربی محاورہ کے مطابق نوکروں اور
خادموں اور غلاموں اور اسی قسم کے دوسرے حاشیہ نشینوں سب پر بولا جاتا ہے.اس طرح اس حدیث میں
گویا ایک نہایت وسیع مضمون مدنظر رکھا گیا ہے.بہر حال اسلام نے آقاؤں اور خادموں کے تعلقات کو
بھی بہترین بنیاد پر قائم کیا ہے.بیاہ شادی کے معاملات میں اسلامی تعلیم بیاہ شادی کا معاملہ بھی تمدنی تعلقات ہی کا حصہ ہے
مگر افسوس ہے کہ دنیا داروں نے اس میدان میں
بھی اپنے خیال کے مطابق مختلف طبقے بنارکھے ہیں اور غیر طبقہ میں رشتہ دینے کو موجب ہتک سمجھا جاتا ہے.سواس کے متعلق ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَارُبَعٍ لِمَا لِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظُفِرُ بِذَاتِ الدِّيْنِ
ل : بخاری کتاب العتق
ے بخاری و مسند احمد جلد ششم صفحه ۱۰۶
Page 799
۷۸۴
تَرِبَتْ يَدَاكَ
یعنی ایک عورت کے ساتھ چار خیالات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے.یا تو دولت کی وجہ
سے بیوی کا انتخاب کیا جاتا ہے اور یا حسب نسب ( یعنی قوم یا خاندان ) کی وجہ سے انتخاب کیا
جاتا ہے اور یا حسن و جمال کی وجہ سے انتخاب کیا جاتا ہے اور یا اخلاقی اور دینی حالت کی بنا پر
انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن اے مرد مومن ! تو ہمیشہ بیوی کا انتخاب دینی اور اخلاقی بنا پر کیا کر
اور ذاتی اوصاف اور ذاتی نیکی کے پہلو کو ترجیح دیا کرو ورنہ یا د رکھ کہ تیرے ہاتھ ہمیشہ
خاک آلو در ہیں گے.“
یہ وہ مبارک تعلیم ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے بلکہ ان کی نسلوں
کو بھی دین ودنیا میں ترقی دینے کی بنیاد بنے کا بھاری ذریعہ ہے.اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی
نمونہ بھی اس معاملہ میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کی شادی اپنے
آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ کر دی تھی اور اس معاملہ میں عربوں کے قدیم رسم ورواج
اور خیالات کی قطعاً پروا نہیں کی.اسی طرح خود آپ نے عربوں کی ہر معروف قوم میں شادی کی یعنی قریش
میں بھی کی غیر قریش میں بھی کی اور بنی اسرائیل میں بھی کی اور عرب میں یہی تین قو میں آباد تھیں مگر افسوس
ہے کہ آج کل کئی مسلمان اپنی قوم سے باہر شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے.مثلاً ایک سیڈ اس بات
پر مصر ہوتا ہے کہ اس کی لڑکی صرف سید کے گھر جائے اور ایک راجپوت کا اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ اس
کی لڑکی صرف راجپوت کی بیوی بنے اور ایک گلے زئی اس بات پر ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی لڑکی
صرف ککے زئی کے ساتھ ہی بیا ہی جائے اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زریں تعلیم اور آپ
کے مبارک اسوہ کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے.مرد و عورت میں حقوق کی مساوات پھر مساوات کی بحث میں مرد عورت کی مساوات کا سوال
بھی بہت اہمیت رکھتا ہے.یعنی جہاں آج کل ایک طبقہ
عورت کو نعوذ باللہ جوتی کی طرح اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتا ہے تو وہاں دوسرا طبقہ اسے ایسی آزادی
دینے پر تلا ہوا ہے کہ گویا وہ انتظامی لحاظ سے بھی خاوند کی نگرانی سے باہر ہوگئی ہے اور پھر یورپ کا ایک
طبقہ تو اسلام کی طرف یہ تعلیم بھی منسوب کرتے ہوئے نہیں شرما تا کہ اسلام عورت میں روح تک کو تسلیم
بخاری کتاب النکاح
Page 800
۷۸۵
تعلم
نہیں کرتا.گویا وہ صرف مشین کی طرح کا ایک جانور ہے جس کی زندگی اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی
ہے مگر قرآن شریف ان سارے باطل خیالات کی تردید فرماتا ہے.چنانچہ سب سے پہلے تو اسلام ہے
دیتا ہے کہ مرد عورت اپنے اعمال کی جد و جہد اور ان کے نتائج کے حصول میں برابر ہیں اور سب کے اعمال کا
نتیجہ یکساں نکلنے والا ہے.چنانچہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
یعنی ”اے لوگو! میں جو تمہارا خالق و مالک ہوں میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے
عمل کو ضائع نہیں کرتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت کیونکہ تم سب ایک ہی نسل کے حصے اور ایک ہی
درخت کی شاخیں ہو.“
اور خاوند بیوی کے مخصوص حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ
یعنی ” جس طرح خاوندوں کے بعض حقوق بیویوں کے ذمہ ہیں اسی طرح بیویوں کے
بعض حقوق خاوندوں کے ذمہ بھی ہیں.“
اس قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اور ذمہ داریوں کے معاملہ میں میاں بیوی برابر ہیں کہ کچھ
پابندیاں خاوند کے ذمہ لگا دی گئی ہیں اور کچھ پابندیاں بیوی کے ذمہ لگا دی گئی ہیں اور دونوں اپنی اپنی
ذمہ داریوں کے متعلق پوچھے جائیں گے.مگر چونکہ انتظامی لحاظ سے گھریلو زندگی کی باگ ڈور بہر حال ایک ہاتھ میں رہنی ضروری ہے اس لئے
اس جہت سے قرآن شریف فرماتا ہے:
الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصُّلِمتُ قُنِتُت - -
یعنی گھریلو زندگی میں مردوں کو عورتوں پر امیر اور نگران رکھا گیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے
فطری قومی میں مردوں کو فضیلت عطا کی ہے اور پھر عورتوں کے اخراجات کی ذمہ داری بھی انہی
پر ہے.پس نیک بیویوں کو بہر حال اپنے خاوندوں کا فرمانبردار رہنا چاہئے.“
لیکن اس انتظامی فرق کو ایک طرف رکھتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ سلوک
ا : آل عمران : ۱۹۶
: سورة البقره : ۲۲۹
: سورة النساء : ۳۵
Page 801
ZAY
کرنے کے متعلق فرماتے ہیں:
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَاهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لَاهْلِي
یعنی ” تم میں سے خدا کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ حسن سلوک
کرنے میں سب سے بہتر ہے اور خدا کے فضل سے میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ
66
بہتر سلوک کرنے والا ہوں.“
اور اس بارے میں قرآن شریف یہ ارشاد فرماتا ہے کہ :
عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَلَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ
فِيْهِ خَيْرًا كَثِيرًاO
یعنی اے مسلمانو! اپنی بیویوں کے ساتھ بہت نیک سلوک کیا کرو اور اگر تم میں سے کوئی
شخص اپنی بیوی کو نا پسند بھی کرتا ہو تو پھر بھی یاد رکھو کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو مگر خدا
نے اس میں تمہارے لئے انجام کے لحاظ سے بہت بڑی خیر مقدر کر رکھی ہو.“
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے مساوات انسانی کے متعلق بہترین تعلیم دی ہے.چنانچہ (۱) سب سے
پہلے اس نے اس اصول کو بیان کیا ہے کہ سب لوگ ایک ہی جنس کی مخلوق اور ایک ہی باپ کی نسل اور ایک
ہی درخت کی شاخیں ہیں اس لئے نسلی لحاظ سے سب کا حق برابر ہے.(۲) اس کے بعد اس نے اس بات
کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نسلی وحدت کے باوجود یہ ممکن ہے کہ جس طرح زمین کے پیٹ میں ایک ہی قسم
کے عناصر مختلف قسم کی صورتیں اور مختلف قسم کے خواص اختیار کر کے مختلف قسم کی معدنیات کی شکل میں ظاہر
ہوتے ہیں اسی طرح مختلف انسان بھی بعد کے حالات کی وجہ سے مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم
ہو کر مختلف اوصاف اختیار کر سکتے ہیں مگر اس فرق کی وجہ سے کسی قوم یا کسی قبیلہ یا کسی فرد کوکسی دوسرے پر
بے جافخر اور تکبر نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ممکن ہے کہ جو قوم یا جوشخص آج نیچے ہے وہ کل کو اوپر ہو جائے.(۳) اس کے بعد اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس وحدت نسلی کے علاوہ مسلمان خصوصیت کے ساتھ ایک
دوسرے کے بھائی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ایمان کے حامل اور ایک ہی دامن رسالت سے وابستہ ہونے کی
وجہ سے ایک ہی روحانی باپ کے بچے ہیں.پس انہیں ہر حال میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہئے.(۴) اس کے بعد اسلام یہ بتاتا ہے کہ بے شک مومنوں میں بھی فرق ہو سکتا ہے مگر یہ فرق ان کے ذاتی
بخاری کتاب النکاح
: سورة النساء : ۲۰
Page 802
ZAZ
اوصاف پر مبنی ہونا چاہئے اور بہر حال خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جود بینداری اور تقویٰ اور
جذ بہ خدمت میں دوسروں سے آگے ہے.(۵) اس کے بعد اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ کسی شخص کے دینی
امتیاز یاد نیوی بڑائی کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہئے کہ قضائی اور عدالتی معاملات میں کوئی فرق ملحوظ رکھا جائے
کیونکہ عدالتی حقوق کے میدان میں سب لوگ قطعی طور پر برابر ہیں.(۶) اس کے بعد اسلام اس زریں
اصول کو بیان کرتا ہے کہ قومی عہدوں
کی تقسیم میں صرف ذاتی اہلیت کو دیکھنا چاہئے اور بلالحاظ امیر وغریب
اور بلالحاظ نسل و خاندان جو شخص بھی کسی عہدہ کا اہل ہو ا سے وہ عہدہ سپر د کرنا چاہئے خواہ وہ کوئی ہو.(۷) اس کے بعد اسلام یہ ارشاد فرماتا ہے کہ گوکسی صاحب عزت شخص کا واجبی اکرام کرنا اچھے اخلاق
کا حصہ ہے مگر تمدنی معاملات میں سب مسلمانوں کو آپس میں اس طرح مل جل کر رہنا چاہئے کہ وہ ایک
خاندان کے افراد نظر آئیں.وہ مجلسوں میں بلا لحاظ امیر وغریب مل جل کر بیٹھیں.اگر کوئی امیر دعوت
کرے تو اس میں غریبوں کو بھی ضرور بلائے اور اگر کوئی غریب دعوت کرے تو امیر اس سے انکار نہ کریں اور
(۸) بالآخر اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ بیاہ شادی کے معاملات میں بیوی کا انتخاب اس کے ذاتی اوصاف اور
ذاتی نیکی کی بنا پر ہونا چاہئے نہ کہ اس کے حسب نسب اور مال و دولت وغیرہ کی بنا پر.اسلام میں دولت کی تقسیم کا نظریہ اس کے بعد دولت کی تقسیم کا سوال آتا ہے جو آج کل کی
اشتراکیت اور سرمایہ داری کی باہمی کشمکش کی جولانگاہ بنا ہوا
ہے.سوگواس بحث کا اصل موقع تو انشاء اللہ دوسری جگہ آئے گا.مگر اس جگہ مختصر طور پر اس قدر بیان کر دینا
ضروری ہے کہ اس اہم سوال کے متعلق بھی اسلام نے ایک ایسی اعلیٰ اور وسطی تعلیم دی ہے جس کی نظیر
کسی دوسری جگہ نہیں ملتی کیونکہ جہاں اسلام نے عام حالات میں دولت پیدا کرنے کے انفرادی حق کو
تسلیم کیا ہے وہاں اس نے ملکی دولت کو سمونے کے لئے ایک ایسی مشینری بھی قائم کر دی ہے کہ اگر اسے
اختیار کیا جائے تو کسی ملک یا کسی قوم کی دولت کبھی بھی عامۃ الناس کے ہاتھوں سے نکل کر چند افراد کے
ہاتھوں میں جمع نہیں ہوسکتی.میں اس جگہ اختصار کے خیال سے اس مشین کے صرف چار پرزوں کے بیان
پر اکتفا کروں گا.ا.سب سے اول نمبر پر اسلامی قانون ورثہ ہے جس کی رو سے ہر مرنے والے کا ترکہ صرف ایک
بچے یا صرف نرینہ اولاد یا صرف اولاد کے ہاتھ میں ہی نہیں جاتا بلکہ سارے لڑکوں اور ساری
لڑکیوں اور بیوی اور خاوند اور ماں اور باپ اور بعض صورتوں میں بھائیوں اور بہنوں اور دوسرے
Page 803
۷۸۸
رشتہ داروں میں ایک نہایت مناسب شرح کے ساتھ تقسیم ہو جاتا ہے.اگر کوئی مسلمان زمیندار
مرتا ہے تو اس کی زمین اس کے سب وارثوں میں تقسیم ہو گی.اگر کوئی دوکاندار مرتا ہے تو اس کی
دوکان کا مال سب وارثوں کو پہنچے گا.اگر کوئی کارخانہ دارفوت ہوتا ہے تو اس کے کارخانے کا حصہ
بھی سارے وارثوں میں بٹے گا وعلی ہذا القیاس.اس طرح گویا اسلام نے دولت کی دوڑ میں
تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد بعض قدرتی روکیں یعنی ہرڈلیس ( HURDLES ) قائم کردی
ہیں اور ہر نسل کے خاتمہ پر ایک روک (یعنی ہر ڈل) سامنے آ کر اس فرق کو کم کر دیتی ہے جو گذشتہ
نسل کے دوران میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے.تقسیم ورثہ کا یہ قانون جس کامل اور مکمل صورت میں
اسلام نے قائم کیا ہے وہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتا اور اس قانون کی تفصیلات پر نظر ڈالنے سے جس
کے بیان کرنے کی اس جگہ گنجائش نہیں ، صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس نظام ورثہ میں صرف ورثا کو
ورثہ پہنچانا ہی مد نظر نہیں ہے بلکہ ملکی دولت کو سمونا بھی اس کا ایک بڑا مقصد ہے.یہی وجہ ہے کہ
اسلام نے ہر مرنے والے کو اپنے مال کے ایک ثلث یعنی ایک تہائی کی وصیت کی اجازت بھی دی
ہے اور یہ وصیت ورثاء کے حق میں جائز نہیں رکھی گئی.گویا اس ذریعہ سے اسلام نے ورثہ کی جبری
تقسیم کے علاوہ اس بات کا دروازہ بھی کھولا ہے کہ نیک دل لوگ اپنے اموال کو مزید مستحقین میں
تقسیم کرنے کا موقع پاسکیں مگر افسوس ہے کہ وصیت کے نظام سے فائدہ اٹھانا تو در کنار آجکل کے
مسلمانوں نے ورثہ کی جبری تقسیم والے حصہ کو بھی پس پشت ڈال رکھا ہے.اور سرمایہ داری کے
خمار نے لڑکیوں اور بیویوں اور ماں باپ تک کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیا ہوا ہے.بہر حال
اسلام کا قانون ورثہ ایک ایسا بابرکت نظام ہے کہ جس کے ذریعہ تھوڑے تھوڑے وقفہ پر ملک کی
دولت کے سمونے کا عمل جاری رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ ہدایت بھی دی ہے
کہ قومی نسل کو بڑھانے کے ذرائع اختیار کرتے رہو.پس جب ایک طرف نسل ترقی کرے گی
اور دوسری طرف ورثہ وسیع ترین صورت میں تقسیم ہو گا تو ظاہر ہے کہ ملکی دولت خود بخود دیتی چلی
جائے گی مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس مبارک تعلیم پر عمل کریں.دوسرے نمبر پر اسلام کا قانون امداد باہمی ہے جسے دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک جبری اور
ے: سورة النساء : ۱۳،۱۲
س : سورۃ بنی اسرائیل آیت : ۳۲ و بخاری کتاب النکاح
بخاری ومسلم
Page 804
۷۸۹
دوسرے طوعی.جبری قانون نظام زکوۃ سے تعلق رکھتا ہے جس کے ذریعہ امیر لوگوں کی دولت پر
حالات کے اختلاف کے ساتھ اڑھائی (۲) فی صد شرح سے لے کر ہیں فی صد شرح تک خاص
ٹیکس عائد کیا گیا ہے اور اس ٹیکس کے ذریعہ جو روپیہ حاصل ہوتا ہے وہ حکومت وقت یا نظام
قومی کی نگرانی کے ماتحت غریبوں اور مسکینوں وغیرہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہمارے آقا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹیکس کی غرض و غایت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ:
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
یعنی زکوۃ کے نظام کا مقصد یہ ہے کہ امیروں کے اموال کا ایک حصہ کاٹ کر غریبوں کی
طرف لوٹایا جائے.“
اس حدیث میں لوٹایا جائے“ کے پر حکمت الفاظ کے استعمال کرنے میں یہ لطیف اشارہ کرنا بھی
مقصود ہے کہ زکوۃ کا ٹیکس کوئی صدقہ و خیرات نہیں ہے جو غریبوں کو بطور احسان دیا جاتا ہے بلکہ وہ امیروں
کی دولت میں غریبوں کا ابدی حق ہے جو انہیں طبعی طریق پر حاصل ہے کیونکہ جیسا کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے.ہر مال کے پیدا کرنے میں غریبوں اور مزدوروں کا بھی کافی دخل ہوتا ہے.زکوۃ کے نظام کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ خدائے حکیم نے ایسے اموال پر زکوۃ کی شرح
زیادہ مقرر فرمائی ہے جو تجارت کے چکر میں نہیں آتے.چنانچہ بند ذخائر پر زکوۃ کی شرح ہیں فی صد ر کھی
گئی ہے.اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں تجارت یا صنعت میں لگے ہوئے روپے میں سے غریب اور
مزدور پیشہ لوگ دوسرے طریق پر بھی کچھ نہ کچھ حصہ لے لیتے ہیں وہاں جمع شدہ ذخائر میں انہیں کوئی حصہ
نہیں ملتا.اس لیے ذخائر میں زکوۃ کی شرح بہت بڑھا کر رکھی گئی ہے.امداد باہمی کے نظام کا دوسرا حصہ طوعی نظام کی صورت میں قائم کیا گیا ہے اس نظام کے ماتحت اسلام
نے غریبوں اور بے کس لوگوں کی امداد پر اتنا زور دیا ہے کہ حق یہ ہے کہ ایک نیک اور خدا ترس انسان کے لیے
یہ صورت بھی قریباً جبری نظام کا رنگ اختیار کر لیتی ہے.گو ذاتی نیکی کے معیار کو بلند کرنے اور اخوت کے
جذبات کو ترقی دینے کے لیے اسے قانون کی صورت نہیں دی گئی.بھوکوں کو کھانا کھلانا ہنگوں کو کپڑا پہنا نا،
مقروضوں کو قرض کی مصیبت سے نجات دلانا ، بیماروں کے لیے علاج کا انتظام کرانا ،غریب مسافروں
کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانا ، قیموں اور بیواؤں کو خاک آلود ہونے سے بچانا وغیرہ وغیرہ ایسی
بخاری کتاب الزكوة
Page 805
490
نیکیاں ہیں جن کی تحریک و تحریص میں قرآن وحدیث بھرے پڑے ہیں اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ذاتی اسوہ اس معاملہ میں یہ تھا کہ رمضان کے مہینہ میں جو غریبوں کی ضروریات کا خاص زمانہ ہوتا ہے اور
اس کے بعد عید بھی آنے والے ہوتی ہے آپ کا ہاتھ غریبوں اور محتاجوں کی امداد میں اس طرح چلتا تھا
جس طرح ایک تیز آندھی چلتی ہے جو کسی روک کو خیال میں نہیں لاتی.الغرض زکوۃ کے جبری نظام اور
دوسرے صدقات کے طوعی نظام کے ذریعہ اسلام نے امیروں کی دولت کو کاٹ کر غریبوں کو دینے اور اس
طرح ملکی دولت کو سمونے کی ایک عظیم الشان مشینری قائم کر رکھی ہے.تیسرے نمبر پر اسلام کا قانون تجارت ہے جس کی رو سے اسلام میں سودی لین دین ممنوع قرار دیا
گیا ہے.آج دنیا کا سمجھدار طبقہ اس بات کو محسوس کر چکا ہے کہ سود ہی وہ چیز ہے جو ملکی دولت کے
توازن کو برباد کرنے کی سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ اس کے ذریعہ غریبوں کا روپیہ سمٹ
سمٹ کر آہستہ آہستہ امیروں کے خزانوں میں جمع ہو جاتا ہے..اور غور کیا جائے تو دراصل سود کی
لعنت ہی سرمایہ داری کے پیدا کرنے کی بڑی موجب ہے.اگر آج سود بند ہو جائے تو اس کا
لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اول تو آہستہ آہستہ ملک کی بڑی بڑی تجارتیں یا تو حکومت کے ہاتھ میں چلی
جائیں گی اور چھوٹی چھوٹی مناسب تجارتوں میں تقسیم ہو کر ملک کی دولت کو خود بخودسمودیں گی اور
دوسرے امیروں کے لیے غریبوں کے پسینہ کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے کا موقع نہیں رہے گا.یہ خیال
که سودی نظام کے بند ہونے سے تجارت ناممکن ہو جائے گی بالکل غلط اور باطل ہے.ایسا خیال
صرف موجودہ ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جب کہ یورپ و امریکہ کے سرمایہ داروں کی نقالی
کے نتیجہ میں سود کا جال وسیع ہو چکا ہے.ورنہ جب سود نہیں تھا اس وقت بھی دنیا کی تجارت چلتی تھی
اور انشاء اللہ آئندہ بھی چلے گی اور یہ خیال کہ اسلام میں صرف وہ سود حرام کیا گیا ہے جو بڑی شرح
کے مطابق چارج کیا جائے یا جس میں سود در سود کا طریق اختیار کیا جائے محض نفس کا ایک دھو کہ
ہے جو اس دلدل میں پھنس جانے کی وجہ سے کمزور لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے ورنہ اسلام نے
ہر قسم کا سود منع کیا ہے اور حق بھی یہی ہے کہ جو چیز ضرر رساں ہے وہ بہر حال ضرر رساں ہے خواہ وہ
تھوڑی مقدار میں ہو یا بڑی مقدار میں.چوتھے نمبر پر اسلام نے جوئے کی قسم کی تمام آمد نیوں کو جن کی بنیاد محض اتفاق پر ہوتی ہے منع
صحیح بخاری
۲ : سورة البقرة آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ و ترمذی ابواب البيوع
Page 806
۷۹۱
قرار دیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی قوم اور ملک کی دولت نا واجب تقسیم کا رستہ کھلتا ہے چنانچہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:.يَا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
یعنی ”اے مسلمانو ! شراب اور جوا اور بتوں کے تھان اور تقسیم کے تیر یقینا ایک شیطانی
عمل ہیں پس تم ان سے بالکل دور ر ہو تا کہ تم کامیاب و با مراد ہوسکو
اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ جوا ان شیطانی اعمال میں سے ہے جو قوموں کی کامیاب زندگی
کو تباہ کرنے والے ہیں اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جوئے میں دولت کے حصول کو محنت اور ہنر مندی پر
مبنی قرار دینے کی بجائے محض اتفاق پر مبنی قرار دیا جاتا ہے جو نہ صرف قومی اخلاق کے لیے مہلک ہے بلکہ
ملک میں دولت کی نا واجب تقسیم کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے.بظاہر یہ ایک معمولی سا حکم نظر آتا ہے مگر اس سے
اس لطیف نظریہ پر بھاری روشنی پڑتی ہے جو اسلام اپنے اقتصادی اور اخلاقی نظام کے متعلق قائم کرنا
چاہتا ہے اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی آمدنی محنت اور ہنر مندی پر مبنی ہونی چاہئے نہ کہ اتفاقی حادثات پر.میسر کا لفظ بھی جو يُسر ( یعنی سہولت اور آسانی سے نکلا ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے
کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جوئے کی آمدنی محنت اور ہنر مندی پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ یونہی بیٹھے بٹھائے
آسانی سے مل جاتی ہے جو اسلام کے اقتصادی نظریہ کے سراسر خلاف ہے.اوپر کی چار اصولی باتیں صرف اختصار کے خیال سے بیان کی گئی ہیں ورنہ اسلام نے اپنے اقتصادی
نظام میں دولت کے سمونے کے بہت سے ذریعے تجویز کئے ہیں اور اسلام کا منشا یہ ہے کہ ایک طرف تو
ذاتی جد و جہد کا سلسلہ جاری رہے اور ہر شخص کے لیے اپنی ذاتی محنت کے پھل کھانے کا رستہ کھلا ہو کیونکہ
دنیا میں محنت اور ترقی کا یہی سب سے بڑا محرک ہے اور دوسری طرف ملکی دولت بھی نا واجب طور پر چند
ہاتھوں میں جمع ہونے سے محفوظ رہے اور یہی وہ وسطی طریق ہے جس پر گامزن ہو کر مسلمان افراط و تفریط
کے رستوں سے بچ سکتے ہیں.معذور لوگوں کی ذمہ واری حکومت پر ہے لیکن اگر با وجود ان ذرائع کے ملک کا کوئی حصہ
: سورة المائدة : ۹۱
بیماری یا بیکاری کی وجہ سے یا زیادہ کنبہ دار ہونے
Page 807
۷۹۲
کے نتیجہ میں اپنی جائز ضروریات کو اپنی جائز آمدنی کے اندر اندر پورا نہ کر سکے تو اس کے متعلق اسلام یہ
ہدایت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اقل ضرورت جو کھانے اور کپڑے اور مکان سے تعلق رکھتی ہے اس کے
پورا کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور اس کا فرض ہے کہ اپنے ملکی محاصل سے ایسے لوگوں کی اقل
بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانہ
میں یہی ہوتا تھا.چنانچہ روایت آتی ہے کہ جب عرب کے علاقہ بحرین کا رئیس مسلمان ہوا تو آنحضر.صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت بھجوائی کہ:
أَفْرِضْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ أَرْضٌ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَعَبَاءَةً
یعنی جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے ان میں سے ہر شخص کو ملکی خزانہ میں سے چار درہم
اور لباس گزارہ کے لئے دیا جائے.“
اسی اصول کی طرف یہ قرآنی آیات اشارہ کرتی ہے کہ :
إنَّ لَكَ الَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرُى ) وَأَنَّكَ لَا تَطْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحى
یعنی دو سچی بہشتی زندگی کی یہ علامت ہے کہ اے انسان ! تو اس میں بھوکا نہ رہے اور نہ ہی
ضروری لباس سے محروم ہو اور نہ ہی سردی سے ٹھٹھرے اور نہ ہی پیاس کی تکلیف اٹھائے اور نہ
ہی دھوپ کی شدت سے جلے.“
پس ہر اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس بات کا انتظام کرے کہ ملک وقوم کا کوئی فردان اقل
ضرورتوں کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائے جو نسل انسانی کی بنیادی ضرورتیں ہیں.خلاصہ کلام یہ کہ جہاں تک
ملکی دولت کی تقسیم کا سوال ہے اسلام نے اول تو قانون ورثہ اور قانون زکوۃ اور قانون تجارت اور حرمت
قمار کے ذریعہ ایسی مشینری قائم کر دی ہے کہ اسے اختیار کرنے کے نتیجہ میں ملکی دولت کبھی بھی عامتہ الناس
کے ہاتھ سے نکل کر چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں جمع نہیں ہوسکتی اور اگر بعض استثنائی حادثات کی وجہ سے
پھر بھی کوئی فرد یا خاندان زندگی کی اقل ضرورتوں سے محروم رہ جائے تو اس کے لئے اسلام اس بات کی
ہدایت فرماتا ہے کہ امیروں کی دولت پر مزید ٹیکس لگا کر غریبوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے کیونکہ ہر انسان
کا جو زندگی کی جدوجہد میں کوتا ہی نہیں کرتا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ بہر حال بھوکا نہ رہے، ننگا نہ ہو اور
سر چھپانے اور سردی گرمی کے بچاؤ سے محروم نہ ہونے پائے.زرقانی بحوالہ ابن منده جلد ۳ صفحه ۳۵۲
: سورة طه : ۱۲۰،۱۱۹
Page 808
۷۹۳
اقتصادی مساوات کے متعلق ایک خاص نکتہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے کیوں نہ
جبری طریق پر دولت کی تقسیم کو بھی مساوی کر دیا
یعنی جس طرح اسلام نے عدالتی معاملات میں پوری پوری مساوات قائم کی اور قومی اور ملکی عہدوں کی تقسیم
کے معاملہ میں پوری پوری مساوات قائم کی اور تمدنی میل ملاقات کے معاملہ میں برادرانہ مساوات کا رنگ
قائم کیا اور سب انسانوں کو ایک باپ کے بیٹے اور سب مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا اسی طرح اس نے
کیوں نہ دولت کو بھی سارے انسانوں میں برابر تقسیم کرنے کی سکیم جاری کی ؟ سواس سوال کا مختصر جواب
یہ ہے کہ اسلام نے ایسا اس لئے نہیں کیا کہ ایسا کرنا ایک ظلم ہوتا اور اسلام ظلم کو مٹانے آیا ہے نہ کہ اسے
قائم کرنے.دولت کی اندھا دھند مساویانہ تقسیم کے یہ معنی ہیں کہ ایک تو لوگوں کی ساری حاصل شدہ دولت
ان سے جبری طور پر چھین لی جائے اور دوسرے آئندہ ان سے دولت پیدا کرنے کی طاقت اور دولت پیدا
کرنے کا حق بھی چھین لیا جائے اور یہ دونوں باتیں ظلم میں داخل ہیں.بے شک قومی حقوق کی خاطر
انفرادی حقوق پر جائز پابندیاں لگائی جاسکتی ہیں اور بے شک افراد سے یہ مطالبہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ وہ
قومی مفاد کی خاطر ضروری قربانی دکھائیں.مگر افراد کے حقوق کو کامل طور پر مٹا کر قوم کے نام پر ان کے
حقوق کو کلیتا غصب کر لینا ظلم میں داخل ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا.علاوہ ازیں اگر غور کیا جائے تو
اس رستہ پر پڑنے سے صرف انفرادیت ہی نہیں ملتی بلکہ بالآخر قومیت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ قوم
افراد کے مجموعہ کا نام ہے اور اگر افراد کو دولت کمانے اور اس کا پھل کھانے کے حق سے محروم کیا جائے گا تو
اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان سے دولت پیدا کرنے کا سب سے زبر دست فطری محرک کھویا جائے گا اور
ظاہر ہے کہ اس محرک کے کھوئے جانے سے وہ بالآخر دولت پیدا کرنے کی قوت کو بھی ضائع کر دیں گے اور
آہستہ آہستہ ان کے دماغی قومی میں انحطاط پیدا ہو جائے گا.بے شک یہ خطرہ اس وقت صرف ایک موہوم
خطرہ نظر آتا ہے لیکن ہر شخص جو صحیح تدبر کا مادہ رکھتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ ایک زمانہ کے بعد اس قسم کے قومی
خطرات حقیقت بن جایا کرتے ہیں.علاوہ ازیں دولت کی کامل طور پر مساویانہ تقسیم خود اشترا کی ممالک میں بھی نہیں پائی جاتی.مثلاً کیا
مارشل سٹالن اور مسٹر مالوٹو واور روس کے دوسرے صنادید اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں جیسا کہ روس کا مزدور
یا کسان کھاتا ہے.یا اسی قسم کا کپڑا پہنتے ہیں جیسا کہ روس کا مزدور اور کسان پہنتا ہے.یا اسی قسم کے
مکانوں میں رہتے ہیں جس میں کہ روس کا مزدور یا کسان رہتا ہے.یا اسی قسم کے حالات میں سفر کرتے
Page 809
۷۹۴
انے
ہیں جن میں کہ روس کا مزدور یا کسان سفر کرتا ہے؟ جب نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر مساوات کہاں رہی؟
صرف فرق یہ ہے کہ کسی نے سرمایہ داری کے رنگ میں ملک کی دولت پر ہاتھ صاف کیا اور کسی نے
اشتراکیت کا پردہ کھڑا کر کے خادم ملت کے رنگ میں اپنے لئے خاص مراعات محفوظ کر لیں حالانکہ فطری
اور طبعی طریق وہ ہے جو اسلام نے قائم کیا ہے.یعنی انفرادی حقوق اور انفرادی جدو جہد بھی جاری رہے
اور غریبوں کو اوپر اٹھانے اور امیروں کی دولت میں سے ایک حصہ کاٹ کر غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے
کا سلسلہ بھی قائم رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظام بھی قائم ہو کہ قومی اور ملکی دولت نا واجب طور پر
چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے محفوظ رہے.در اصل سارا دھوکا اس بات سے لگا ہے کہ انسانی حقوق کی اقسام پر غور نہیں کیا گیا.انسانی حقوق دو قسم
کے ہوتے ہیں.(۱) ایک وہ حقوق ہیں جو حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں جیسے کہ مثلاً عدل وانصاف کا قیام
یا قومی عہدوں کی تقسیم وغیرہ.اور (۲) دوسرے وہ حقوق ہیں جو یا تو فطری اور قدرتی رنگ میں حاصل
ہوتے ہیں جیسے آسمانی طاقتیں اور دماغی قوی وغیرہ اور یا وہ انفرادی کوشش اور انفرادی جد و جہد کے نتیجہ میں
حاصل ہوتے ہیں جیسے دولت یا مکسوب علم وغیرہ.اسلام نے نہایت حکیمانہ طریق پر ان دونوں قسم کے
حقوق میں اصولی فرق ملحوظ رکھا ہے.یعنی جہاں تک ان انسانی حقوق کا تعلق ہے جو حکومت کے ذمہ ہوتے
ہیں اسلام نے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کامل مساوات قائم کی ہے اور مختلف قوموں اور مختلف انسانوں میں
قطعاً کوئی فرق پیدا ہونے نہیں دیا لیکن جہاں دوسری قسم کے حقوق کا دائرہ شروع ہوتا ہے جو فطری قویٰ
اور انفرادی جدو جہد سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اسلام نے ایک مناسب حد تک دخل دے کر مختلف طبقات
اور مختلف افراد کے فرق کو سمونے کی تو ضرور کوشش کی ہے لیکن ظلم و جبر کے رنگ میں سارے فرقوں کو یکسر
مٹانے کا طریق اختیار نہیں کیا.اور حق یہ ہے کہ اس میدان میں سارے فرقوں کو مٹا نا ممکن بھی نہیں ہے.مثلاً جسمانی طاقتوں کے فرق کو کون مٹا سکتا ہے؟ دماغی قوتوں کے فرق کو کون مٹا سکتا ہے؟ اور جب یہ فرق
نہیں مٹائے جاسکتے تو ظاہر ہے کہ ان فرقوں کے طبعی نتائج بھی نہیں مٹائے جا سکتے.ہاں چونکہ انسان
مدنی الاصل صورت میں پیدا کیا گیا ہے اور اس کی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ہم جنس لوگوں
کے ساتھ مل کر اور جہاں تک ممکن ہو ان کے لئے قربانی کرتے ہوئے زندگی گزارے.اس لئے اسلام
نے یہ ضرور کیا ہے کہ انسان کی انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے اس سے بعض قومی ضرورتوں کے لئے
قربانیوں کا مطالبہ کیا ہے اور اس مطالبہ کو اس انتہائی حد تک پہنچا دیا ہے جو ایک انسان کی انفرادیت کو
Page 810
۷۹۵
مٹانے اور ظلم کا طریق اختیار کرنے کے بغیر اس کے اردگرد کے گرے ہوئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اوپر
اٹھانے کے لئے ضروری ہے.یہ وہ نکتہ ہے جسے سمجھ لینے کے بعد اسلامی مساوات اور اشتراکیت کا مسئلہ
خود بخود حل ہو جاتا ہے بشرطیکہ کوئی شخص دیانت داری کے ساتھ اسے سمجھنے کے لئے تیار ہو.اسلام ایک وسطی نظریہ پیش کرتا ہے ایک اور اصولی بات جو اسلام کے اقتصادی نظام کے
متعلق یاد رکھنی چاہئے یہ ہے کہ انسانی زندگی کے متعلق
اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ اس میں ہر وقت ایک جدوجہد کی کیفیت قائم رہنی چاہئے اور درحقیقت
زندگی ایک پیہم حرکت اور مسلسل جدوجہد کا ہی نام ہے اور انسان کی ساری ترقی اسی پیہم حرکت اور
اسی مسلسل سعی کے ساتھ وابستہ ہے.پس اسلام کسی ایسے نظام کا موید نہیں ہوسکتا جس میں انسان کو
جدو جہد کے میدان سے نکل کر دوسرے کے کمائے ہوئے مال کو بیٹھے بیٹھے کھانے یا دوسرے کے سہارے
پر کھڑے ہو کر زندگی گزارنے کا رستہ اختیار کرنا پڑے.بے شک اسلام بھی انفرادی زندگی کے لئے بعض
خارجی سہارے مہیا کرتا اور ان سے واجبی فائدہ اٹھانے کا سامان پیدا کرتا ہے مگر اس کا اصل زور اس بات
پر ہے کہ ہر انسان خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور اپنے ہاتھ کی طاقت یا اپنے دماغ کی قوت سے اپنے لئے
زندگی کا رستہ بنائے.وہ خارجی سہاروں کو ایک زائد امدادی حیثیت تو ضرور دیتا ہے مگر صرف انہی پر
کامل تکیہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا.اسی لئے قرآن شریف ورثہ کے ذریعہ حاصل کئے ہوئے مالوں کو
بیٹھ کر کھانے والوں کے متعلق فرماتا ہے:
تَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكلَّا لَمَّانَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّا جَمَّا
یعنی " تم لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ورثہ کے مالوں کو کھانا چاہتے ہو اور خواہش رکھتے ہو کہ
یہ جمع شدہ مال کبھی ختم نہ ہو اور تم ذخیرہ شدہ مال و دولت سے عشق لگائے بیٹھے ہو.“
اس لطیف آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ خدائے اسلام کو ایسی زندگی پسند
نہیں جو انسان کو جد وجہد اور سعی و عمل کے میدان سے نکال کر کسی خاص کھونٹے کے ساتھ باندھ
دے.کیونکہ اس طرح آہستہ آہستہ انسان کے فطری قوی زنگ آلود ہو کر ضائع ہو جاتے ہیں.مگر ہم دیکھتے
ہیں کہ سرمایہ داری اور اشتراکیت یعنی کمیونزم دونوں انسانوں کو جد و جہد والی زندگی سے نکال کر دوسروں پر
تکیہ کر کے بیٹھ جانے کا رستہ کھولتے ہیں یعنی جہاں سرمایہ داری جمع شدہ روپے کا کھونٹا گاڑ کر اس کے
ل : سورة الفجر : ۲۱،۲۰
Page 811
۷۹۶
ساتھ انسان کو باندھ دیتی ہے وہاں اشتراکیت یعنی کمیونزم دوسری انتہا کی طرف لے جا کر اور حکومت کے
کھونٹے کے ساتھ باندھ کر انسان کو گو یا سلانا چاہتی ہے.اس سے ظاہر ہے کہ گو یہ انتہا ئیں جدا جدا ہیں مگر
حقیقتاً سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں میں یہی اصول چلتا ہے کہ انسان کو انفرادی جد و جہد کے میدان
سے نکال کر کسی مضبوط کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جائے جہاں وہ ہر وقت چوکس رہنے کی ضرورت محسوس
کرنے کے بغیر آرام کی زندگی گزار سکے.پس غور کیا جائے تو یہ دونوں افراط و تفریط کی راہیں ہیں جن سے
خدائے اسلام لوگوں کو بچا کر جدوجہد کے سرگرم میدان میں کھڑا رکھنا چاہتا ہے.اشتراکیت کا اصول کیا
ہے؟ یہی ناکہ قوم کے سب افراد مل کر متحدہ زندگی گزاریں اور خواہ بعض افراد دوسروں سے کمزور ہوں
اور بعض مضبوط اور خواہ بعض سست ہوں اور بعض چوکس ہوں وہ گریں تو اکٹھے گریں اور کھڑے ہوں
تو اکٹھے کھڑے ہوں.مگر غور کرو کہ کیا یہ بھی سرمایہ داری کی طرح ایک غیر طبعی سہارا نہیں جو انفرادی
جد و جہد سے انسان کو غافل کرنے کا موجب ہو سکتا ہے؟ بے شک اسلام نے بھی کمزور افراد کے لئے
ملک وقوم کا سہارا مہیا کیا ہے.مگر اس نے کمال دانش مندی سے اس سہارے پر پورا بھروسہ نہیں ہونے دیا
اور انفرادی بوجھ کی اصل ذمہ داری افراد پر رکھی ہے اور زائد سہارا صرف جزوی امداد کے طور پر یا غیر معمولی
حالات کے لئے مہیا کیا گیا ہے.پس اسلام ہی وہ وسطی مذہب ہے جس نے سرمایہ داری اور اشتراکیت
دونوں انتہاؤں سے بچتے ہوئے ایک درمیانی رستہ کھولا ہے.وہ نہ تو جمع شدہ اموال کے ساتھ انسان
کو باندھ کر اسے سرمایہ داری کے طریق پر بیکار کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے اشتراکیت کے اصول پر کلیڈ
حکومت کے سہارے پر رکھ کر اس کی انفرادی جد و جہد کو کمزور کرتا ہے.چنانچہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے
ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -
یعنی ”اے مسلمانو! ہم نے تمہیں ایک وسطی امت بنایا ہے تا کہ تم ہر قسم کی انتہاؤں کی
66
طرف جھک جانے والی قوموں کے لئے خدا کی طرف سے نگران رہو.“
خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے اپنے اقتصادی نظام میں وسطی طریق اختیار کیا ہے اور اگر کوئی
دل و دماغ رکھنے والا شخص اشتراکیت کے مقابلہ پر اسلام کے اقتصادی نظام کے متعلق منصفانہ غور کرنا
چاہے تو اس کے لئے اس نکتہ میں بھی بھاری سبق ہے کہ گوانتہاؤں کا فرق ضرور ہے یعنی سرمایہ داری ایک
: سورة البقرة : ۱۴۴
Page 812
292
انتہا پر واقع ہے اور اشتراکیت دوسری انتہا پر مگر بہر حال اشتراکیت بھی ایک دوسری صورت میں اسی
مصیبت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے جو اس کے مقابل کی انتہا یعنی سرمایہ داری نے پیش کر رکھی
ہے.یعنی یہ دونوں نظام انسان کو جد و جہد کے میدان سے نکال کر کسی نہ کسی کھونٹے کے ساتھ باندھنا
چاہتے ہیں اور یہ صرف اسلام ہی ہے جس نے وسطی رستہ اختیار کر کے ایک طرف تو انسان کی انفرادی
جد و جہد کو قائم رکھا ہے اور دوسری طرف خاص حالات کے پیش نظر نیز قوم میں اخوت اور اتحاد کی روح قائم
رکھنے کے لئے بعض خارجی سہارے بھی مہیا کر دئے ہیں اور یہی وہ رستہ ہے جس سے انسان کا دماغ کند اور
منجمد ہونے سے بچ سکتا ہے ورنہ جو لعنت آج دنیا کے سامنے سرمایہ داری نے پیدا کی ہے وہی کچھ عرصہ
کے بعد ایک مختلف صورت میں اشتراکیت کے ذریعہ دنیا کے سامنے آنے والی ہے.استثنائی حالات میں خوراک کی مساویانہ تقسیم دولت کی تقسیم کے متعلق اس حکیمانہ نظریہ کے
باوجود جس میں عام حالات کے ماتحت جبری
طریق کے اختیار کرنے کے بغیر دولت کو منصفانہ رنگ میں سمونے کا انتظام کیا گیا ہے تا کہ انفرادی جد و جہد
کا محرک بھی قائم رہے اور ملکی دولت چند ہاتھوں میں جمع بھی نہ ہونے پائے.اسلام اس بات کی تعلیم دیتا
ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسے خاص حالات پیدا ہو جائیں کہ کسی ملک یا قوم یا بستی کی خوراک کے ذخیرہ میں کمی
آجائے یعنی ایک حصہ کے پاس تو زائد خوراک موجود ہو اور دوسرے حصہ کے پاس اس کی اقل ضرورت
سے بھی کم ہو یا بالکل ہی نہ ہو تو اس قسم کے ہنگامی حالات میں خوراک کی مساویانہ تقسیم کا جبری نظام بھی
جاری کیا جاسکتا ہے.چنانچہ روایت آتی ہے کہ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ فَأَصَابَنَا جُهُدٌ حَتَّى هَمَمُنَا
أَنْ نَنْحَرَ بَعْضَ ظَهْرِنَا فَاَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعْنَا أَزْوَادَنَا
یعنی ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلے مگر رستہ میں ہمیں خوراک
کی سخت کمی پیش آگئی.حتی کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اپنی سواریوں کے بعض اونٹ ذبح کر دیں.اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگوں کے خوراک کے ذخیرے اکٹھے
کر لئے جائیں پس ہم نے سب ذخیرے اکٹھے کر لئے.اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان میں سے سب کو مساویانہ راشن بانٹنا شروع کر دیا.“
ل : مسلم باب استحباب خلط الازواد
Page 813
۷۹۸
پھر ایک اور روایت آتی ہے کہ:
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ
الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُ مِائَةٍ فَخَرَجْنَا وَ كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ فَأَمَرَا بُوْعُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ
الْجَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزْوَ دَى تَمَرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ فَلَمْ يَكُنُ
يُصِيبُنَا إِلَّا تَمُرَةٌ تَمْرَةٌ
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک پارٹی ساحل سمندر کی طرف روانہ کی اور
اس سریہ کا امیر (اپنے مقرب صحابی ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر فرمایا اور یہ پارٹی تین سو صحابہ پر
مشتمل تھی.راوی کہتا ہے کہ ہم اس سر یہ میں نکلے لیکن ( رستہ بھول جانے کی وجہ سے ) ابھی
ہم اس کے رستہ میں ہی تھے کہ ہمارا زاد کم ہونا شروع ہو گیا.اس پر ابوعبیدہ نے حکم دیا کہ سب
لوگوں کی خوراک کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے تو یہ سارا جمع شدہ ذخیرہ دو تو شہ دان بنا.اس کے
بعد ابوعبیدہ ہمیں اس ذخیرہ میں سے تھوڑی تھوڑی خوراک تقسیم کرواتے تھے حتی کہ یہ ذخیرہ اتنا
کم ہو گیا کہ بالآخر ہمارا راشن صرف ایک کھجور فی کس پر آ گیا.“
اس روایت سے یہ بھاری اصول مستنبط ہوتا ہے کہ خاص ہنگامی حالات میں خوراک کے انفرادی
ذخائر کو اکٹھا کر کے قومی ذخیرہ میں منتقل کیا جا سکتا ہے.اسی طرح ایک دوسری روایت آتی ہے کہ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا اَرْمَلُوا فِي الْغَزُوِ اَوْ
قَلَّ طَعَامُ عَيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبِ وَاحِدِثُمَّ اقْتَسَمُوا بَيْنَهُمْ فِي
إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ
یعنی " آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اشعر قبیلہ کے لوگوں کا یہ طریق ہے کہ
جب کسی سفر میں انہیں خوراک
کا ٹوٹا پڑ جاتا ہے یا حضر کی حالت میں ہی ان کے اہل وعیال کی
خوراک میں کمی آجاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ سب لوگوں کی خوراک ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں
اور پھر اس جمع شدہ خوراک کو ایک ناپ کے مطابق سب لوگوں میں مساویانہ طریق پر بانٹ دیتے
ہیں.یہ وہ لوگ ہیں جن کا میرے ساتھ حقیقی جوڑ ہے اور میرا ان کے ساتھ حقیقی جوڑ ہے.“
بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ سيف البحر
بخاری باب الشركة في الطعام
Page 814
۷۹۹
یہ الفاظ جس بلند اور شاندار روح کا اظہار کر رہے ہیں وہ کسی تشریح کی محتاج نہیں مگر افسوس ہے کہ
دنیا نے اپنے اس عظیم الشان محسن کی قدر نہیں کی.خلاصہ کلام یہ کہ اسلام میں دولت کی تقسیم کے متعلق چار بنیادی اصول تسلیم کئے گئے ہیں:
اول تقسیم ورثہ اور نظام زکوۃ کے قیام اور سود اور جوئے کی حرمت کے ذریعہ ملکی دولت کو چند ہاتھوں
میں جمع ہونے سے بچایا جائے.دوم : مگر دولت پیدا کرنے کے انفرادی حق کو قائم رکھا جائے تا کہ کام کرنے کا ذاتی محرک بھی قائم
رہے اور افراد کے دماغ منجمد نہ ہونے پائیں.سوم : جولوگ با وجود ان ذرائع کے کسی خاص معذوری کی وجہ سے اپنی اقل ضروریات کا سامان بھی
پیدا نہ کرسکیں ان کی ضروریات کے پورا کرنے کا حکومت انتظام کرے.چہارم : خاص ہنگامی حالت میں جب کہ خوراک کی خطرناک قلت پیدا ہو جائے.تمام انفرادی
ذخیروں کو جمع کر کے ایک مرکزی قومی ذخیرہ قائم کر لیا جائے تا کہ سب لوگوں کو اقل خوراک کا مساویانہ
راشن ملتا ر ہے اور یہ نہ ہو کہ ملک کا ایک حصہ تو عیش اڑائے اور دوسرا قوت لا یموت سے بھی محروم ہو.دینی اور روحانی امور میں مساوات اس کے بعد ہم اس مساوات کی بحث کو لیتے ہیں جو دینی اور
روحانی امور سے تعلق رکھتی ہے سو جاننا چاہئے کہ گو لا مذہب
لوگوں اور دنیا داروں کو اس میدان کی اہمیت پر اطلاع نہ ہو مگر قرب الہی کی تڑپ رکھنے والوں اور نجات
اخروی کے متلاشیوں کے نزدیک یہ میدان دنیا کی زندگی سے بھی بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ قابل توجہ
ہے اور الحمد للہ کہ اس میدان میں بھی اسلامی تعلیم نے صحیح مساوات کے تر از وکو پوری طرح برابر رکھا
ہے.سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں دوسرے مذاہب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خدا کے کلام کا نزول
اور اس کے نبیوں اور رسولوں کا ظہور صرف خاص خاص قوموں کے ساتھ ہی مخصوص رہا ہے اور دنیا کی
دوسری قو میں اس عظیم الشان روحانی نعمت سے کلی طور پر محروم رہی ہیں مثلاً یہودی لوگ اپنے سوا کسی دوسری
قوم کو اس روحانی انعام کا حق دار نہیں سمجھتے اور اسی طرح ہندو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام صرف
آریہ ورت تک محدود رہا ہے اور کسی دوسرے ملک اور دوسری قوم نے اس سے حصہ نہیں پایا اور عملاً عیسائی
قوم بھی بنی اسرائیل کے باہر کسی نبی اور رسول وغیرہ کی قائل نہیں.الغرض جہاں دنیا کی ہر قوم اس روحانی
نعمت کو صرف اپنے آپ تک محدود قرار دے رہی ہے اور کسی دوسری قوم کو اس کا حق دار نہیں
سمجھتی وہاں
Page 815
اسلام با نگ بلند یہ تعلیم دیتا ہے کہ جس طرح خدا نے اپنی مادی نعمتوں کو ہر قوم اور ہر ملک پر وسیع کر رکھا
ہے اور کسی ایک قوم یا ایک ملک کے ساتھ مخصوص نہیں کیا مثلاً اس کا سورج ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا
ہے.اس کی ہوا سارے کرہ ارض کو یکساں گھیرے ہوئے ہے.اس کا پانی ساری دنیا کو سیراب کرتا ہے
وغیرہ وغیرہ.اسی طرح خدا نے اپنی روحانی نعمتوں
کو بھی کسی خاص قوم یا خاص ملک تک محدود نہیں کیا بلکہ
ہر قوم اور ہر ملک کو اس سے حصہ دیا ہے.کیونکہ اسلام کی تعلیم کے مطابق دنیا کا خدا کسی خاص قوم یا خاص
ملک کا خدا نہیں بلکہ ساری دنیا اور ساری قوموں کا خدا ہے اور وہ ایک ایسا مقسط اور عادل حکمران ہے کہ
سب مخلوق کو ایک نظر سے دیکھتا ہے.چنانچہ فرماتا ہے:
وَانْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ
یعنی ”دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کی طرف خدا نے اپنی طرف سے کوئی رسول
نہ بھیجا ہوتا کہ وہ انہیں ہوشیار کر کے نیکی بدی کا رستہ دکھا دے اور ترقی کی راہیں بتا دے.“
یہ الفاظ کیسے مختصر ہیں مگر غور کرو تو ان کے اندر روحانی اور دینی مساوات کا ایک عظیم الشان فلسفہ مخفی ہے
جس نے دنیا کی ساری قوموں کو خدا کی توجہ کا یکساں حق دار قرار دے کر ایک لیول پر کھڑا کر دیا ہے اور اس
خیال کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا ہے کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا خدایا صرف آریہ ورت کا خدا ہے اور دوسری
قوموں کے لئے اس کی محبت اور انصاف کی آنکھ بالکل بند ہے.الغرض اسلام نے روحانی مساوات کے
میدان میں پہلا اصول یہ قائم کیا ہے کہ کلام الہی اور نبوت ورسالت کا وجود کسی خاص قوم یا خاص ملک کے
ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت میں ہر قوم اس عظیم الشان روحانی انعام سے حصہ پاتی رہی
ہے.کیونکہ ہر قوم خدا کی پیدا کردہ ہے اور خدا سے یہ بعید ہے کہ ایک ظالم باپ کی طرح اپنے ایک بیٹے کو
حصہ دے اور دوسرے کو ہمیشہ کے لئے محروم کر دے.اسی ضمن میں نجات اور قرب الہی کے حصول کا سوال آتا ہے.اکثر قوموں نے دنیوی اور اخروی امور
میں بھی گویا ایک اجارہ داری کا رنگ اختیار کر رکھا ہے اور ایک خاص نسلی طبقہ کو خدا کا مقرب اور نجات کا
مستحق قرار دے کر باقی سب کو عملاً محجوب اور ملعون گردانا ہے جسے
کبھی بھی نجات اور قرب الہی کی ٹھنڈی ہوا
نہیں پہنچ سکتی.مثلاً یہودی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف ایک اسرائیلی نسل کا انسان ہی نجات کا مستحق
ہے اور باقی سب لوگ خواہ وہ کیسے ہی نیک ہوں جہنم کا ایندھن ہیں.اسی طرح عیسائیوں نے گونسلی رنگ
سورة فاطر
۲۵ :
Page 816
۸۰۱
میں نجات کو محدود نہیں کیا مگر بہت سے دینی حقوق و فرائض کو ایک خاص گروہ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے
جسے پر یسٹ ہڈ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے چنانچہ عیسائیوں کے متعدد دینی امور بلکہ بعض تمدنی امور بھی
ایک پریسٹ کی وساطت کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتے.اسی طرح ہندوؤں میں بعض دینی حقوق کو صرف
برہمن کا ورثہ قرار دیا گیا ہے اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں.گویا ان قوموں نے نہ صرف دوسری
اقوام کو نجس اور پلید قرار دے کر دھتکار دیا ہے بلکہ خود اپنے اندر بھی دینی اور مذہبی امور میں ناگوار
طبقات کا وجود تسلیم کر کے خدائی انعامات کو بعض خاص طبقوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے مگر اسلام کا دامن
ان سب ناپاک جذبہ داریوں کے داغ سے پاک ہے بلکہ جس طرح اس نے دنیوی حقوق میں پوری پوری
مساوات قائم کی ہے اسی طرح اس نے دینی امور میں بھی انصاف اور مساوات کے ترازو کوکسی طرف
جھکنے نہیں دیا چنا نچہ اس بارے میں ایک اصولی قرآنی آیت اوپر کی بحث میں گزرچکی ہے جو یہ ہے.إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ الْقُكُمْ
یعنی اے لوگو سن رکھو کہ تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ معزز اور زیادہ مقرب وہ شخص
ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ نیک اور زیادہ صالح ہے.“
اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرب الہی کے حصول کے معاملہ میں کسی قوم یا کسی طبقہ کی خصوصیت نہیں
بلکہ سب گورے کالے، بڑے چھوٹے ، طاقتور کمزور ، مرد عورت خدا کا قرب حاصل کرنے کے معاملہ
میں برابر ہیں اور آگے آنے کے لئے صرف ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی کی ضرورت ہے.ان مختصر الفاظ میں
خدا تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ ہو کر سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں
اور اپنا قرب عطا کرنے میں ذاتی تقویٰ و طہارت کے سوا کسی اور بات کا خیال نہیں کرتے تو پھر دوسروں کو
تو بدرجہ اولیٰ یہ چاہئے کہ ذاتی اوصاف کے سوا کسی اور بات پر اپنے انتخاب
کی بنیاد نہ رکھا کریں.پھر دینی امور میں جزا اور سزا اور انعام و الزام کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ نُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ =
یعنی ”جو شخص بھی خواہ وہ کوئی ہو ایک ذرہ بھر بھی نیکی کرتا ہے وہ ہم سے اس کا اجر پائے گا
لے یہ صرف موجود الوقت عیسائیوں کا حال ہے ورنہ خود حضرت مسیح نے تو غیر اسرائیلی اقوام کو سنتے کہہ کر دھتکار دیا
ہے.مثلا دیکھئے مرقس باب ۱۷ آیت ۲۴ تا ۲۷
: سورة الحجرات : ۱۴
ے : سورۃ الزلزال : ٩،٨
Page 817
۸۰۲
اور اس کا کسی خاص طبقہ سے تعلق رکھنا اسے نیک عمل کے پھل سے محروم نہیں کرسکتا ) اور اسی
طرح جو شخص بھی کوئی بدی کرتا ہے وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا (اور اس کا کسی خاص طبقہ سے تعلق
رکھنا اسے اس کی بدی کے نتیجہ سے بچا نہیں سکتا ).“
پھر فرماتا ہے:
وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَطَرِى تِلْكَ آمَانِيُّهُمْ ۖ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ
عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ
یعنی ” یہودی اور عیسائی لوگ دعوی کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہود یا نصاری کے سوا جنت میں
نہیں جاسکتا.یہ ان لوگوں کی محض خام خیالی ہے اور ایک ہوس سے زیادہ حقیقت نہیں
رکھتی.تو انہیں کہہ دے کہ اگر تم اس دعوئی میں بچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ.ہاں بے شک جس شخص
نے اپنے تئیں خدا کے سپر د کر دیا یعنی اس پر سچا ایمان لایا اور پھر نیک عمل کئے تو وہ خواہ کوئی ہو
خدا سے اپنا اجر پائے گا اور ایسے لوگوں پر خدا کے حضور کوئی خوف و حزن نہیں آئے گا.“
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نجات پانے اور قرب الہی کے حصول کے لئے صرف قومی یا رسمی رنگ
میں یہودی یا عیسائی یا کسی اور مذہب کی طرف منسوب ہونا ہرگز کافی نہیں بلکہ نجات اور قرب الہی کے لئے
سچا ایمان اور عمل صالح ضروری ہے.پس جو شخص بھی یہ دو باتیں یعنی سچا ایمان اور عمل صالح اپنے اندر
پیدا کرتا ہے تو پھر خواہ وہ قومی یا نسلی رنگ میں کوئی ہو وہ خدا کی طرف سے ثواب اور انعام کا مستحق ہوگا.یہ آیت ضمنا مسلمانوں کو بھی ہوشیار کرتی ہے کہ وہ محض مسلمان کہلانے پر تسلی نہ پائیں کیونکہ خدا تعالیٰ کو
خالی ناموں سے سروکار نہیں بلکہ اس کی نظر حقیقت پر ہے.پھر دینی فرائض کی ادائیگی کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
يَؤُمُ الْقَوْمَ أَقْرَتُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَأَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا
بِالسُّنَّةِ سَوَاءٌ فَاقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَاكْثَرُهُمْ سِنًّا - وَفِي رِوَايَةٍ
فَلْيَومُهُمْ اَحَدُهُمْ وَاَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَتُهُمْ -
یعنی اے مسلمانو! جب تم آپس میں فریضہ نماز کی ادائیگی کے لئے اکٹھے ہو ( جو اسلام
ا: سورة البقرة : ۱۱۲ ۱۱۳
ترمذی کتاب الصلوة س : صحیح مسلم کتاب الصلوة
Page 818
۸۰۳
میں سب سے اہم اور سب سے وقیع تر عبادت ہے ) تو اس وقت اپنا امام بنانے کے لئے صرف
یہ دیکھا کرو کہ تم میں سے قرآن
کا علم کس شخص کو زیادہ حاصل ہے.پس جو شخص بھی قرآنی علم میں
زیادہ ہوا سے نماز میں اپنا امام بنالیا کرو اور اگر چند آدمی علم قرآن میں برابر ہوں تو پھر ان میں
سے جو شخص سنت رسول کے علم میں زیادہ ہوا سے امام بنایا کرو اور اگر چند آدمی سنت کے علم
میں بھی برابر ہوں تو پھر ان میں سے جس شخص نے خدا کی راہ میں پہلے ہجرت کی ہوا سے امام بنایا
کرو اور اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر جو شخص عمر میں زیادہ ہوا سے اپنا امام بنالیا کرو اور
ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نمازوں میں مسلمانوں کا امام ہر وہ شخص ہوسکتا ہے
جو ان میں سے ہے اور کسی خاص طبقہ کی تخصیص نہیں مگر امامت کا زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو
دین کا زیادہ علم رکھتا ہے.“
الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کے ہر میدان میں حقیقی مساوات قائم فرمائی ہے
اور سوسائٹی کی ہر نا واجب کش مکش کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا ہے اور جسم اور روح دونوں کی اصلاح کی ہے
اور یہ وہ مساوات ہے جس کی نظیر یقیناً کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی.اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَّبَارِک وَسَلّم - مساوات اسلامی کے متعلق یہ نوٹ سپرد قلم کرنے کے بعد ہم پھر اپنے اصل
مضمون کی طرف لوٹتے ہیں.سریہ دومتہ الجندل شعبان ۶ ہجری مطابق دسمبر ۶۲۷ء اب بڑی سرعت کے ساتھ اسلامی
اثر کا دائرہ وسیع ہورہا تھا اور عرب
کے دور دراز کناروں میں بھی اسلام کی تبلیغ پہنچ رہی تھی.مگر اس کے ساتھ دور کے علاقوں میں مخالفت بھی
بڑھ رہی تھی اور جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے انہیں اپنے ہم قبیلہ لوگوں کی طرف سے سخت مظالم
سہنے پڑتے تھے اور ان مظالم سے ڈر کر بہت سے کمزور طبع لوگ اسلام کے اظہار سے رکے رہتے تھے.اس لئے اب جنگی مہموں کی اغراض میں اس غرض کا اضافہ ہو گیا کہ ایسے قبائل کی طرف فوجی دستے روانہ
کئے جائیں جن میں بعض لوگ دل میں اسلام کی طرف مائل تھے مگر مظالم کے ڈر کی وجہ سے وہ اسلام کو
قبول کرنے سے رکھتے تھے.گویا ان دستوں کے بھیجوانے کی غرض مذہبی آزادی کا قیام تھی جس پر اسلام
خاص طور پر زور دیتا ہے.ا : سورۃ الانفال : ۴۰
Page 819
۸۰۴
اس غرض وغایت کے ماتحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان ۶ھ میں ایک فوجی دستہ
عبدالرحمن بن عوف کی کمان میں دومۃ الجندل کے دور دراز مقام کی طرف روانہ فرمایا یے ناظرین کو یاد ہوگا
کہ اسی جگہ کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ۴ ھ میں قیام امن کی غرض سے تشریف لے گئے تھے
اور اس طرح یہ علاقہ آج سے دو سال قبل اسلامی دائرہ اثر میں داخل ہو چکا تھا اور وہاں کے باشندے
اسلامی تعلیم سے غیر مانوس نہیں رہے تھے بلکہ غالبا ان میں سے ایک حصہ اسلام کی طرف مائل تھا مگر
اپنے رؤساء اور اہل قبیلہ کی مخالفت کی وجہ سے جرات نہیں کر سکتے تھے.بہر حال آپ نے ہجری کے چھٹے
سال میں ایک بڑا فوجی دستہ عبدالرحمن بن عوف کی امارت میں جو کبار صحابہ میں سے تھے دومۃ الجندل
کی طرف روانہ فرمایا.اس سریہ کی تیاری اور روانگی کے متعلق ابن اسحاق نے عبداللہ ابن عمر سے یہ دلچسپ روایت نقل کی
ہے کہ ایک دفعہ جب ہم چند لوگ جن میں حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن بن عوف بھی
شامل تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے ، ایک انصاری نوجوان نے حاضر ہو کر آپ
سے دریافت کیا کہ 'یا رسول اللہ ! مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا.” وہ جو
اخلاق میں سب سے افضل ہے.“ اس نے کہا اور یا رسول
اللہ ! سب سے زیادہ متقی کون ہے ، آپ نے
فرمایا ” وہ جو موت کو زیادہ یا درکھتا اور اس کے لئے وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے.اس پر وہ انصاری
نوجوان خاموش ہو گیا اور آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کے گروہ! پانچ بدیاں
ایسی ہیں جن کے متعلق میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ کبھی میری امت میں پیدا ہوں کیونکہ وہ جس قوم
میں رونما ہوتی ہیں اسے تباہ کر کے چھوڑتی ہیں.اول: یہ کہ کبھی کسی قوم میں فاحشہ اور بدکاری نہیں پھیلی اس حد تک کہ وہ اسے برملا کر نے لگ
جائیں کہ اس کے نتیجہ میں ایسی بیماریاں اور وبائیں نہ ظاہر ہونی شروع ہوگئی ہوں جوان سے پہلے
لوگوں میں نہیں تھیں.دوم : کبھی کسی قوم میں تول اور ناپ میں بد دیانتی کرنے کی بدی نہیں پیدا ہوئی کہ اس کے نتیجہ میں
اس قوم پر قحط اور محنت اور شدت اور حاکم وقت کے ظلم وستم کی مصیبت نازل نہ ہوئی ہو.سوم : کبھی کسی قوم نے زکوۃ اور صدقات کی ادائیگی میں ستی و غفلت نہیں اختیار کی کہ اس کے نتیجہ
ا یہ لفظ دال کی زیر سے بھی بولا جاتا ہے
ابن سعد
Page 820
۸۰۵
میں ان پر بارشوں کی کمی نہ ہو گئی ہو.حتی کہ اگر خدا کو اپنے پیدا کردہ جانوروں اور مویشیوں کا خیال نہ ہو
تو ایسی قوم پر بارشوں کا سلسلہ بالکل ہی بند ہو جائے.چہارم کبھی کسی قوم نے خدا اور اس کے رسول کے عہد کو نہیں توڑا کہ ان پر کوئی غیر قوم ان کے
دشمنوں میں سے مسلط نہ کر دی گئی ہو جو ان کے حقوق کو غصب کر نے لگ جائے.پنجم کبھی کسی قوم کے علماء اور ائمہ نے خلاف شریعت فتوے دے دے کر شریعت کو اپنے مطلب کے
166
مطابق نہیں بگاڑنا چاہا کہ ان کے درمیان اندرونی لڑائی اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع نہ ہو گیا ہو.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زریں تقریر قوموں کی ترقی و تنزل کے اسباب پر بہترین تبصرہ ہے
اور اگر مسلمان چاہیں تو ان کے لئے موجودہ زمانہ میں بھی یہ ایک بہترین سبق ہے.اس کے بعد آپ اپنے مقرب صحابی عبدالرحمن بن عوف سے مخاطب ہوئے اور فرمایا.ابن عوف!
میں
تمہیں ایک سریہ پر امیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں تم تیار رہو.“ چنانچہ دوسرے دن صبح کے وقت عبدالرحمن
بن عوف آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر انہی کا عمامہ لے کر
باندھا اور بلال کو حکم دیا کہ ایک جھنڈا ان کے سپرد کر دیا جائے.اور پھر آپ نے حضرت عبدالرحمن بن
عوف کے ماتحت صحابہ کا ایک دستہ متعین کر کے ان سے فرمایا:
خُذْهُ يَا ابْنَ عَوْفٍ فَاغْرُوا جَمِيعًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَا تَغْلُوا وَلَاَ
تَغْدِرُوا وَلَا تُمَتِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيْدًا فَهَذَا عَهْدُ اللَّهِ وَسِيْرَةُ نَبِيِّهِ فِيُكُمْ
یعنی ”اے ابن عوف اس جھنڈے کو لے لو اور پھر تم سب خدا کے رستہ میں جہاد کے لئے
نکل جاؤ اور کفار کے ساتھ لڑ ونگر دیکھنا کوئی بددیانتی نہ کرنا اور نہ کوئی عہد شکنی کرنا اور نہ دشمن کے
مردوں کے جسموں
کو بگاڑنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا.یہ خدا کا حکم ہے اور اس کے نبی کی سنت.“
اس روایت میں غالبا راوی نے سہو ا عورتوں کا ذکر چھوڑ دیا ہے ورنہ دوسری جگہ صراحت آتی ہے کہ
آپ جب کوئی دستہ بھجواتے تھے تو یہ بھی تاکید فرماتے تھے کہ عورتوں کو قتل نہ کرنا اور نہ بوڑھے پیر فرتوت
لوگوں
کو قتل کرنا اور نہ ایسے لوگوں کو قتل کرنا جن کی زندگی مذہبی خدمت کے لئے وقف ہو.اس کے بعد
ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۸۸ حالات سریہ دومۃ الجندل
: ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۸۹٬۸۸
سے : مسلم وموطا وابوداؤ دو طحاوی جن کا حوالہ سیرۃ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم دوم میں گزر چکا ہے
Page 821
1+7
آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو ہدایت فرمائی کہ وہ دومتہ الجندل کی طرف جائیں اور کوشش کریں کہ صلح
صفائی سے فیصلہ ہو جائے.کیونکہ اگر وہ لوگ جنگ وجدال سے دستکش ہو کر اطاعت قبول کر لیں تو یہ سب
سے اچھی بات ہے.اور آپ نے عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا کہ اس صورت میں مناسب ہوگا کہ تم
ان لوگوں کے رئیس کی لڑکی سے شادی کرلو یا
اس کے بعد آپ نے اس سریہ کو رخصت فرمایا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سات سو صحابیوں
کو ساتھ لے کر دومۃ الجندل کی طرف جو عرب کے شمال میں تبوک سے شمال مشرق کی طرف شام کی سرحد
کے قریب واقع ہے، روانہ ہو گئے.جب یہ اسلامی لشکر دومہ میں پہنچا تو شروع شروع میں تو دومہ کے لوگ
جنگ کے لئے تیار نظر آتے تھے اور مسلمانوں کو تلوار کی دھمکی دیتے تھے یا مگر آہستہ آہستہ عبدالرحمن بن
عوف کے سمجھانے پر وہ اس ارادے سے باز آ گئے اور چند دن کے بعد ان کے رئیس اصبغ بن عمر کلبی نے جو
عیسائی تھا عبدالرحمن بن عوف کی تبلیغ سے بطیب خاطر اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اس کی قوم
میں سے بھی بہت سے لوگ جو غالباً پہلے سے دل میں اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے مسلمان ہو گئے اور
جولوگ اپنے دین پر قائم رہے انہوں نے بھی بشرح صدر اسلامی حکومت کے ماتحت آجانا منظور کر لیا ہے
اس طرح بڑی خیر وخوبی کے ساتھ یہ ہم اختتام کو پہنچی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق
عبد الرحمن بن عوف دومۃ الجندل کے رئیس اصبغ بن عمر کی لڑکی تماضر کے ساتھ شادی کر کے مدینہ میں
واپس لوٹ آئے اور خدا کے فضل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت سے عبدالرحمن بن عوف
کے ہاں اسی تماضر کے بطن سے ایک ایسا لڑ کا پیدا ہوا جو خاص فدائیان اسلام میں سے نکلا اور علم وفضل
کے اس مرتبہ کو پہنچا کہ وہ اپنے وقت میں اسلام کے چوٹی کے علماء میں سے سمجھا جاتا تھا.اس کا نام
ابوسلمہ زہری تھا.سریہ حضرت علی بطرف فدک شعبان ۶ ہجری مدینہ میں یہودی قوم پر ان کی اپنی غدار یوں اور
فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے جو تبا ہی آئی تھی وہ تمام
عرب کے یہودیوں کے دل میں ایک کانٹا بن کر کھٹک رہی تھی اور غزوہ بنوقریظہ کے بعد سے جب کہ
مدینہ میں یہود کا خاتمہ ہو گیا.خیبر کی بستی جو حجاز کے یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھی اسلام کے خلاف
ابن سعد
ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۵،۶۴
دار قطنی بحوالہ زرقانی حالات سریہ دومتہ الجندل
دار
زرقانی حالات سریہ دومۃ الجندل
Page 822
۸۰۷
سازشوں کا اڈہ بن گئی تھی اور اس جگہ کے یہودی جو عادة سخت کینہ ور اور حاسد و ظالم واقع ہوئے تھے اسلام
کومٹانے اور مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کی کوشش میں سرگرم رہتے تھے.چنانچہ بالآخر یہی حالات جنگ
خیبر کا باعث بن گئے جوے ہجری کے ابتداء میں وقوع میں آئی اور جس کے نتیجہ میں خیبر کا علاقہ اسلامی
حکومت میں شامل ہو گیا.اب جس واقعہ کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ بھی اسی سلسلہ میں منسلک ہے.شعبان ۶ ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ قبیلہ بنوسعد بن بکر اور خبیر
کے یہودیوں میں مسلمانوں کے خلاف باہم سرگوشیاں ہورہی ہیں اور یہ کہ بنو سعد اہل خیبر کی اعانت
میں اپنی طاقتوں کو جمع کر رہے ہیں.اس اطلاع کے ملتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کی
کمان میں صحابہ کا ایک دستہ روانہ فرمایا جو دن کو چھپتے اور رات کو سفر کرتے ہوئے فدک کے پاس پہنچ گئے
جس کے قریب یہ لوگ جمع ہورہے تھے.یہاں مسلمانوں کو ایک بدوی شخص ملا جو بنو سعد کا جاسوس
تھا.حضرت علیؓ نے اسے پکڑ کر قید کر لیا اور اس سے بنو سعد اور اہل خیبر کے حالات دریافت کئے.پہلے تو
اس نے بالکل لاعلمی اور بے تعلقی کا اظہار کیا مگر آخر وعدہ معافی لے کر اس نے سارا راز کھول دیا اور پھر
مسلمان لوگ اس شخص کو اپنا گائیڈ بنا کر اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں بنو سعد جمع ہورہے تھے اور اچانک حملہ
کر دیا.اس اچانک حملہ کی وجہ سے بنو سعد گھبرا کر میدان سے بھاگ نکلے اور حضرت علی مال غنیمت لے کر
مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے اور اس طرح یہ خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا ہے
سریہ حضرت ابوبکر بطرف بنو فزارہ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک
دستہ حضرت ابوبکر کی کمان میں بنوفزارہ کی طرف روانہ
فرمایا.یہ قبیلہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پر کار تھا اور اس دستہ میں سلمہ بن اکوع بھی شامل ہوئے
جو مشہور تیرانداز اور دوڑنے میں خاص مہارت رکھتے تھے.سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز
کے قریب اس قبیلہ کی قرارگاہ کے پاس پہنچے اور جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر نے ہمیں
حملہ کا حکم دیا.ہم قبیلہ فزارہ سے لڑتے ہوئے ان کے چشمہ تک جا پہنچے اور مشرکین کے کئی آدمی مارے گئے
جس کے بعد وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ہم نے کئی آدمی قید کر لئے.سلمہ روایت کرتے ہیں کہ
بھاگنے والے لوگوں میں ایک پارٹی بچوں اور عورتوں کی تھی جو جلدی جلدی ایک قریب کی پہاڑی کی طرف
بڑھ رہی تھی.میں نے ان کے اور پہاڑی کے درمیان تیر پھینکنے شروع کئے.جس پر یہ پارٹی خائف ہوکر
: ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۵
ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۵ و زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۶۲
Page 823
۸۰۸
کھڑی ہوگئی اور ہم نے انہیں قید کر لیا.ان قیدیوں میں ایک عمر رسیدہ عورت بھی تھی جس نے اپنے
اوپر سرخ چھڑے کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کی ایک خوبصورت لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی.میں ان سب
کو گھیر کر حضرت ابوبکر کے پاس لے آیا اور آپ نے یہ لڑکی میری نگرانی میں دے دی.پھر جب ہم مدینہ
میں آئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ لڑکی لے لی اور اسے مکہ بھجوا کر اس کے عوض میں بعض
ان مسلمان قیدیوں کی رہائی حاصل کی جو اہل مکہ کے پاس محبوس تھے.اُم قرفہ کے قتل کا غلط واقعہ سریہ حضرت
ابو بکر کی جگہ جس کا ذکراو پر گذر چکا ہے ابن سعد نے ایک
ایسے سریہ کا ذکر کیا ہے جس میں زید بن حارثہ امیر تھے.یعنی ابن سعد
اس سریہ میں حضرت ابوبکر کی بجائے زید بن حارثہ کو امیر بیان کرتا ہے اور تفاصیل میں بھی کسی قدر اختلاف
کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ ہم بن فزارہ کی گوشمالی کے لیے تھی جو وادی قری کے پاس آباد تھے اور جنہوں
نے مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ پر چھاپہ مار کر اس کا سارا مال و اسباب چھین لیا تھا.اس مفسد گروہ کی
روح رواں ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام اُم قرضہ تھا جو اسلام کی سخت دشمن تھی.جب یہ عورت اس لڑائی
میں پکڑی گئی تو زید کی پارٹی کے ایک شخص قیس نامی نے اس عورت
کو قتل کر دیا.اور ابن سعد اس
قتل کا قصہ
یوں بیان کرتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں دو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے اور پھر ان اونٹوں کو
مختلف جہات میں ہنکایا گیا جس کے نتیجہ میں یہ عورت درمیان میں سے چر کر دو ٹکرے ہوگئی اور اس کے
بعد اس عورت کی لڑکی سلمہ بن اکوع کے سپر د کر دی گئی..یہی قصہ کسی قدر اختصار اور اجمال اور اختلاف
کے ساتھ ابن اسحاق نے بھی بیان کیا ہے.اس روایت کی بنا پر سر ولیم میور نے جو دوسرے یورپین مؤرخین کی نسبت زیادہ تفصیل دینے کا عادی
ہے اس واقعہ کو مسلمانوں کی وحشیانہ روح کی مثال میں بڑے شوق سے اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے
بلکہ سرولیم نے اسے اپنی کتاب میں درج کرنے کی وجہ ہی یہی لکھی ہے کہ اس مہم میں مسلمان ایک
ظالمانہ فعل کے مرتکب ہوئے تھے.چنانچہ میور صاحب لکھتے ہیں:
اس سال مسلمانوں کو بہت سی مہموں میں مدینہ سے نکلنا پڑا مگر یہ سب قابل ذکر نہیں ہیں
البتہ میں ان میں سے ایک مہم کے ذکر سے رک نہیں سکتا کیونکہ اس کا انجام مسلمانوں کی طرف
صحیح مسلم کتاب الجہاد باب التنفيل و سفن ابوداؤ د بروایت زرقانی حالات سریہ زید الی أم قرفه
: ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۵
۳ : ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۸۳
Page 824
1+9
سے ایک نہایت ظالمانہ فعل پر ہوا تھا.14
جو مؤرخ ایک واقعہ کو دوسرے واقعات پر محض اس وجہ سے ترجیح دے کر اسے اپنی کتاب کی زینت
بناتا ہے کہ اس میں کسی قوم کے ظلم وستم کا ثبوت ملتا ہے وہ درحقیقت ایک غیر جانبدار محقق کہلانے کا
حقدار نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ اس بات کی تحقیق کی طرف توجہ کریگا کہ آیا یہ
ظلم وستم کا واقعہ کوئی اصلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے ہاتھ سے اس کی ایک
دلیل نکل جاتی ہے.بہر حال میور صاحب نے اس واقعہ کو خاص شوق کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کیا
ہے مگر جیسا کہ ابھی ظاہر ہو جائے گا یہ واقعہ بالکل غلط اور قطعاً بے بنیاد ہے اور نقل و عقل ہر دو طرح سے
اس کا بناوٹی ہونا ثابت ہے.عقلی طریق پر تو یہ جاننا چاہیے کہ ایک عورت کو جس پر قتل کا الزام نہیں ہے قید کر کے ٹھنڈے لمحات
میں قتل کرنا اور پھر قتل بھی اسی طریق پر کرنا جو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے یہ تو ایک بہت دور کی بات
ہے.اسلام تو عین جنگ کے میدان میں بھی عورت کے قتل کو تختی کے ساتھ روکتا ہے اور ہم جہاد کی اصولی
بحث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان درج کر چکے ہیں جو آپ نے عورتوں کے قتل کو ممنوع
فرماتے ہوئے جاری فرمایا تھا.چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر میدان جنگ میں کسی دشمن قبیلہ کی
ایک عورت مقتول پائی گئی تو باوجود اس کے کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کن حالات میں اور کس کے
ہاتھ سے قتل ہوئی ہے آپ اسے دیکھ کر بہت ناراض ہوئے اور صحابہ سے یہ تاکیداً فرمایا کہ ایسا کام
آئندہ نہیں ہونا چاہئے.اسی طرح یہ ذکر بھی اوپر گذر چکا ہے کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی
دستہ روانہ فرماتے تھے تو منجملہ اور نصیحتوں کے صحابہ سے ایک نصیحت یہ بھی فرماتے تھے کہ کسی عورت اور
بچے کو قتل نہ کرنا.ان اصولی ہدایات کے ہوتے ہوئے صحابہ کے متعلق اور صحابہ میں سے بھی زید بن حارثہ کے متعلق جو
گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے یہ خیال کرنا کہ انھوں نے کسی عورت کو اس طریق پر قتل
کیا یا کروایا تھا جوا بن سعد نے بیان کیا ہے ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتا.بیشک روایت میں قتل کرنے کا فعل
زید کی طرف منسوب نہیں کیا گیا بلکہ ایک دوسرے مسلمان کی طرف کیا گیا ہے لیکن جب کہ یہ واقعہ زید کی
لے لائف آف محمد حاشیه صفحه ۳۳۶
بخاری کتاب الجہاد باب
قتل الصبيان والنساء
مسلم کتاب الجہاد باب تحریم قتل النساء والصبيان
Page 825
۸۱۰
کمان میں ہوا تو بہر حال اس کی آخری ذمہ داری بھی زید پر ہی کبھی جائے گی اور زید کے متعلق یہ خیال کرنا
کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جانتے ہوئے اس قسم کے کام کی اجازت دی ہوگی ہرگز
قابل قبول نہیں ہو سکتا.بیشک اگر کوئی عورت کسی جرم کی مرتکب ہوتی ہے تو وہ اس جرم کی سزا پائے گی اور
کسی مذہب کی شریعت اور کسی ملک کے قانون نے عورت کو جرم کی سزا سے مستثنے نہیں رکھا اور آئے دن
عورتوں کی سزا بلکہ قتل کے جرم میں پھانسی تک کے واقعات چھپتے رہتے ہیں مگر محض مذہبی عداوت کی وجہ
سے یا شرکت جنگ کی وجہ سے کسی عورت کا قتل کرنا اور قتل بھی اسی طریق پر کرنا جو اس روایت میں بیان ہوا
ہے ایک ایسا فعل ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولی ہدایت اور ساری اسلامی تاریخ صریح طور پر
رڈ کرتی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ عورت مجرم تھی اور جیسا کہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے اس نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا تھا.اس لیے اس کے خلاف جائز طور پر قتل کی سزا جاری کی
جا سکتی تھی تو یہ درست ہے.مگر سوال یہ ہے کہ جب صحابہ نے اُم قرفہ سے سخت اور زیادہ خونی دشمنوں اور
پھر مرد دشمنوں کو بھی کبھی اس طرح قتل نہیں کیا تو یہ خیال کرنا کہ زید بن حارثہ جیسے واقف کا صحابی کی کمان
میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہو گا ہر گز قابل تسلیم نہیں ہوسکتا.پس معقولی رنگ میں اس
قصہ کا جھوٹا اور بناوٹی ہونا ظاہر وعیاں ہے اور کوئی غیر متعصب شخص اس میں شبہ کی گنجائش نہیں دیکھ سکتا.اب رہا منقولی طریق سواوّل تو ابن سعد یا ابن اسحاق نے اس روایت کی کوئی سند نہیں دی اور بغیر
کسی معتبر سند کے اس قسم کی روایت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایت اور صحابہ کے عام اور
معروف طریق کے خلاف ہو ہر گز قبول نہیں کی جاسکتی.دوسرے یہ کہ یہی واقعہ حدیث کی نہایت معتبر کتب
صحیح مسلم اور سنن ابوداؤد میں بیان ہوا ہے مگر اس میں اُم قرفہ کے قتل کئے جانے کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے
اور بعض دوسری تفصیلات میں بھی اس بیان کو ابن سعد وغیرہ کے بیان سے اختلاف ہے.اور چونکہ صحیح
احادیث عام تاریخی روایات سے یقیناً اور مسلمہ طور پر بہت زیادہ مضبوط اور قابل ترجیح ہوتی ہیں.اس لئے
صحیح مسلم اور سنن ابوداؤد کی روایت کے سامنے ابن سعد وغیرہ کی روایت کوئی وزن نہیں رکھتی.یہ امتیاز
اور بھی نمایاں ہو جاتا ہے جب ہم اس بات کو مدنظر رکھیں کہ جہاں ابن سعد اور ابن اسحاق نے اپنی روایتوں
ل : زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۶۳
یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ابن اسحاق نے بروایت ابن ہشام صرف یہ لکھا ہے کہ ام قرفہ کوفتی کے ساتھ قتل کروا دیا گیا
اور اس کی تفصیل نہیں دی تفصیل ابن سعد نے دی ہے.
Page 826
All
کو یونہی بلا سند بیان کیا ہے وہاں امام مسلم اور ابو داؤد نے اپنی روایتوں کو پوری پوری سند دی ہے اور ویسے
بھی محدثین کی احتیاط کے مقابلہ میں جنہوں نے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے مؤرخین کی عام روایت کوئی
حقیقت نہیں رکھتی.صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں یہ واقعہ جس طرح بیان ہوا ہے وہ اوپر درج کیا جا چکا ہے.اس میں
ام قرفہ کے قتل کا ذکر تک نہیں ہے.بیشک مسلم اور ابوداؤد کی روایت میں ام قرفہ کا نام مذکور نہیں ہے
اور امیر کا نام بھی زید کی بجائے ابو بکر درج ہے مگر اس کی وجہ سے یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ مہم اور ہے کیونکہ
باقی جملہ اہم تفصیلات ایک ہیں.مثلاً :
-1
دونوں روایتوں میں یہ تصریح ہے کہ یہ ہم بن فزارہ کے خلاف تھی.دونوں میں یہ ذکر موجود ہے کہ بنو فزارہ کی رئیس ایک بوڑھی عورت تھی.دونوں میں اس عورت کے قید کئے جانے کا ذکر ہے.دونوں میں یہ ذکر ہے کہ اس عورت کی ایک لڑکی بھی تھی جو ماں کے ساتھ قید ہوئی.۵.دونوں میں یہ ذکر ہے کہ یہ لڑ کی سلمہ بن اکوع کے حصہ میں آئی تھی.اس کے علاوہ اور بھی بعض باتوں میں اشتراک ہے.اب غور کرو کہ کیا ان اہم اور بنیادی اشتراکات
کے ہوتے ہوئے کوئی شخص شبہ کر سکتا ہے کہ یہ دوالگ الگ واقعات ہیں.مگر ہم صرف عقلی استدلال پر ہی
اکتفا نہیں کرتے بلکہ گذشتہ محققین نے بھی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں وہی
واقعہ بیان ہوا ہے جو ابن سعد نے دوسرے رنگ میں درج کیا ہے.چنانچہ علامہ زرقانی اور امام
سہیلی اور علامہ حلبی سے نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے جوا بن سعد اور ابن اسحاق نے
ام قرفہ والے قصہ میں غلط طور پر بیان کیا ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر اس بات کا ثبوت کہ یہ وہی واقعہ
ہے یہ ہے کہ طبری نے ان دونوں روایتوں کو پہلو بہ پہلو بیان کر کے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ
دونوں ایک ہی واقعہ ہیں ہے
الغرض یہ بات بالکل یقینی ہے کہ مسلم اور ابوداؤد کی سلمہ بن اکوع والی روایت میں وہی واقعہ بیان کیا
گیا ہے جسے ابن سعد اور ابن ہشام نے اُم قرفہ کے سریہ کے نام سے غلط طور پر درج کیا ہے اور چونکہ
شرح مواهب جلد ۲ صفحه ۱۶۴
: سيرة حلبیہ جلد ۳ حالات سریہ ابوبکرالی بنی فزارہ ہے : طبری طبع یورپ جلد ۳ صفحه ۱۵۵۷ تا ۱۵۵۹ نیز صفحه۱۵۹۲
الروض الانف جلد ۲ صفحه ۳۶۱
Page 827
۸۱۲
صحاح کی روایت جو سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور ایک شریک واقعہ کی زبان سے مروی ہے بہر حال
ابن سعد اور ابن ہشام کی غیر مستند روایت سے قابل ترجیح ہے اس لئے اس بات میں ہرگز کوئی شبہ نہیں رہتا
کہ ام قرفہ کے ظالمانہ قتل کا واقعہ ایک بالکل جھوٹا اور بے بنیاد واقعہ ہے جو کی مخفی دشمن اسلام اور منافق
کی مہربانی سے بعض تاریخی روایتوں میں راہ پا گیا ہے اور حق یہ ہے کہ اس سریہ کی حقیقت اس سے بڑھ کر
اور کچھ نہیں جو مسلم اور ابو داؤد نے بیان کی ہے.کسی غلط واقعہ کا تاریخ میں درج ہو جانا کوئی تعجب کی بات
نہیں کیونکہ اس قسم کی مثالیں ہر قوم اور ہر ملک کی تاریخ میں ملتی ہیں.لیکن یہ ضرور ایک تعجب کی بات ہے کہ
سرولیم جیسا انسان اس غلط واقعہ کو بغیر کسی تحقیق کے اپنی کتاب میں جگہ دے اور اس بات کا برملا اعتراف
کرے کہ اس کے اندارج کی وجہ محض یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کے ایک ظالمانہ فعل کی مثال ملتی ہے.اہل خیبر کی شرارت اور ابورافع یہودی کا جن یہودی رؤساء کی مفسدانہ انگیخت
اشتعال انگیزی سے ۵ ہجری کے آخر میں مسلمانوں
قتل رمضان ۶ ہجری مطابق جنوری ۶۲۸ء کے خلاف جنگ احزاب کا خطرناک فتنہ بر پا ہوا تھا
ان میں سے حیی بن اخطب تو بنو قریظہ کے ساتھ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا لیکن سلام بن ابی الحقیق جس
کی کنیت ابورافع تھی ابھی تک خیبر کے علاقہ میں اسی طرح آزاد اور اپنی فتنہ انگیزی میں مصروف تھا بلکہ
احزاب کی ذلت بھری نا کامی اور پھر بنو قریظہ کے ہولناک انجام نے اس کی عداوت کو اور بھی زیادہ کر دیا تھا
اور چونکہ قبائل غطفان کا مسکن خیبر کے قریب تھا اور خیبر کے یہودی اور نجد کے قبائل آپس میں گویا ہمسائے
تھے اس لئے اب ابورافع نے جو ایک بہت بڑا تاجر اور امیر کبیر انسان تھا دستور بنالیا تھا کہ نجد کے وحشی اور
جنگجو قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں وہ کعب بن
اشرف کا پورا پورا مثیل تھا.چنانچہ اس زمانہ میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس نے غطفانیوں کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملہ آور ہونے کے لئے اموال کثیر سے امداد دی تھی اور تاریخ سے ثابت ہے
کہ ماہ شعبان میں بنو سعد کی طرف سے جو خطرہ مسلمانوں کو پیدا ہوا تھا اور اس کے سد باب کے لئے حضرت
علی کی کمان میں ایک فوجی دستہ مدینہ سے روانہ کیا گیا تھا اس کی تہ میں بھی خیبر کے یہودیوں کا ہاتھ تھا کے
جوابو رافع کی قیادت میں یہ سب شرارتیں کر رہے تھے.: ابن ہشام جلد ۲ صفحه ۱۶۲
: ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۵
: فتح الباری جلدے صفحہ ۲۶۳
Page 828
۸۱۳
مگرا بورافع نے اسی پر بس نہیں کی.اس کی عداوت کی آگ مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس کی آنکھوں میں خار کی طرح کھٹکتا تھا.چنانچہ بالآخر اس نے یہ تدبیر
اختیار کی کہ جنگ احزاب کی طرح نجد کے قبائل غطفان اور دوسرے قبیلوں کا پھر ایک دورہ کرنا شروع کیا
اور انہیں مسلمانوں کے تباہ کرنے کے لئے ایک لشکر عظیم کی صورت میں جمع کرنا شروع کر دیا.جب نوبت
یہاں تک پہنچ گئی اور مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے پھر وہی احزاب والے منظر پھرنے لگ گئے تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ خزرج کے بعض انصاری حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب
اس فتنہ کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کسی طرح اس فتنہ کے بانی مبانی ابورافع کا خاتمہ کر دیا جائے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سوچتے ہوئے کہ ملک میں وسیع کشت وخون کی بجائے ایک
مفسد اور فتنہ انگیز آدمی کا مارا جانا بہت بہتر ہے ان صحابیوں کو اجازت مرحمت فرمائی اور عبداللہ بن
عتیک انصاری کی سرداری میں چار خزرجی صحابیوں کو ابو رافع کی طرف روانہ فرمایا مگر چلتے ہوئے تاکید
فرمائی کہ دیکھنا کسی عورت یا بچے کو ہر گز قتل نہ کرنا ہے چنانچہ ۶ ھ کے ماہ رمضان میں یہ پارٹی روانہ
ہوئی اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ اپنا کام کر کے واپس آگئی.اور اس طرح اس مصیبت کے بادل مدینہ
کی فضا سے ٹل گئے.اس واقعہ کی تفصیل بخاری میں جس کی روایت اس معاملہ میں صحیح ترین روایت ہے
مندرجہ ذیل صورت میں بیان ہوئی ہے.براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک
پارٹی ابورافع یہودی کی طرف روانہ فرمائی اور ان پر عبداللہ بن عتیک انصاری کو امیر مقررفرمایا.ابورافع کا یہ قصہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ دیا کرتا تھا اور آپ کے خلاف
لوگوں کو ابھارتا تھا اور ان کی مدد کیا کرتا تھا.جب عبداللہ بن عتیک اور ان کے ساتھی ابو رافع
کے قلعہ کے قریب پہنچے اور سورج غروب ہو گیا تو عبداللہ بن عتیک نے اپنے ساتھیوں کو
پیچھے چھوڑا اور خود قلعہ کے دروازے کے پاس پہنچے اور اس کے قریب اس طرح چادر لپیٹ کر
بیٹھ گئے جیسے کوئی شخص کسی حاجت کے لئے بیٹھا ہو.جب قلعہ کا دروازہ بند کرنے والا شخص
دروازہ پر آیا تو اس نے عبداللہ کی طرف دیکھ کر آواز دی کہ اے شخص میں قلعہ کا دروازہ بند
: ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۶
موطا كتاب الجهاد
: ابن ہشام جلد ۲ صفحه ۱۶۲
ابن ہشام
ه : ابن سعد
Page 829
۸۱۴
کرنے لگا ہوں تم نے اندر آنا ہو تو جلد آ جاؤ.عبداللہ چادر میں لیٹے لیٹائے جلدی سے دروازہ
کے اندر داخل ہو کر ایک طرف کو چھپ گئے اور دروازہ بند کرنے والا شخص دروازہ بند کر کے اور
اس کی کنجی ایک قریب کی کھونٹی سے لٹکا کر چلا گیا.اس کے بعد عبد اللہ بن عتیک کا اپنا بیان ہے کہ میں اپنی جگہ سے نکلا اور سب سے پہلے میں
نے قلعہ کے دروازے کا قفل کھول دیا تا کہ ضرورت کے وقت جلدی اور آسانی کے ساتھ باہر
نکلا جا سکے.اس وقت ابورافع ایک چوبارے میں تھا اور اس کے پاس بہت سے لوگ مجلس
جمائے بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے.جب یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے اور خاموشی ہوگئی
تو میں ابورافع کے مکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا اور میں نے یہ احتیاط کی کہ جو
دروازہ میرے راستہ میں آتا تھا اسے میں آگے گزر کر اندر سے بند کر لیتا تھا.جب میں ابورافع
کے کمرے میں پہنچا تو اس وقت وہ چراغ بجھا کر سونے کی تیاری میں تھا اور کمرہ بالکل تاریک
تھا.میں نے آواز دے کر ابو رافع کو پکارا.جس کے جواب میں اس نے کہا.کون ہے؟ بس میں
اس آواز کی سمت کا اندازہ کر کے اس کی طرف لپکا اور تلوار کا ایک زور دار دار کیا مگر اندھیرا بہت
تھا اور میں اس وقت گھبرایا ہوا تھا اس لئے تلوار کا وار غلط پڑا اور ابورافع چیخ مار کر چلا یا جس پر میں
کمرہ سے باہر نکل گیا.تھوڑی دیر بعد میں نے پھر کمرہ کے اندر جا کر اپنی آواز کو بدلتے ہوئے
چھا.ابو رافع یہ شور کیسا ہوا تھا ؟ اس نے میری بدلی ہوئی آواز کو نہ پہچانا اور کہا.تیری ماں
تجھے کھوئے مجھ پر ابھی ابھی کسی شخص نے تلوار کا وار کیا ہے.میں یہ آواز سن کر پھر اس کی طرف
لپکا اور تلوار کا وار کیا.اس دفعہ وار کاری پڑا مگر وہ مرا پھر بھی نہیں جس پر میں نے اس پر ایک
تیسرا وار کر کے اسے قتل کر دیا.اس کے بعد میں جلدی جلدی دروازے کھولتا ہوا مکان سے باہر نکل آیا، لیکن جب میں
سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو ابھی چند قدم باقی تھے کہ میں سمجھا کہ میں سب قدم اتر آیا ہوں
جس پر میں اندھیرے میں گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی (اور ایک روایت میں یوں ہے کہ
پنڈلی کا جوڑ اتر گیا مگر میں اسے اپنی پگڑی سے باندھ کر گھسٹتا ہوا باہر نکل گیا لیکن میں نے
اپنے جی میں کہا کہ جب تک ابو رافع کے مرنے کا اطمینان نہ ہو جائے میں یہاں سے نہیں
جاؤں گا چنانچہ میں قلعہ کے پاس ہی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا.جب صبح ہوئی تو قلعہ کے اندر
Page 830
۸۱۵
سے کسی کی آواز میرے کان میں آئی کہ ابورافع تاجر حجاز وفات پا گیا ہے.اس کے بعد میں اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے ساتھیوں میں آملا اور پھر ہم نے مدینہ میں
آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو رافع کے قتل کی اطلاع دی.آپ نے سارا واقعہ سن کر
مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنا پاؤں آگے کرو.میں نے پاؤں آگے کیا تو آپ نے دعا مانگتے
ہوئے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا جس کے بعد میں نے یوں محسوس کیا کہ گویا مجھے کوئی
166
تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی.ایک دوسری روایت میں ذکر آتا ہے کہ جب عبد اللہ بن عتیک نے ابورافع پر حملہ کیا تو اس کی بیوی
نے نہایت زور سے چلانا شروع کیا جس پر مجھے فکر ہوا کہ اس کی چیخ و پکارسن کر کہیں دوسرے لوگ نہ ہوشیار
ہو جائیں اس پر میں نے اس کی بیوی پر تلوار اٹھائی مگر پھر یہ یاد کر کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
عورتوں کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے میں اس ارادہ سے باز آ گیا.ابورافع کے قتل کے جواز کے متعلق ہمیں اس جگہ کسی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں.ابورافع کی
خون آشام کا رروائیاں تاریخ کا ایک کھلا ہوا ورق ہیں اور اس سے ایک ملتے جلتے واقعہ میں ایک مفصل
بحث کتاب کے حصہ دوم میں سے کعب بن اشرف کے قتل کے بیان میں گزر چکی ہے جس کے اعادہ کی اس
جگہ ضرورت نہیں اصولاً اس قدر یا درکھنا چاہئے کہ :
-1
-۲
اس وقت مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں چاروں طرف سے مصیبت میں مبتلا تھے اور ہر طرف
مخالفت کی آگ شعلہ زن تھی.اور گویا سارا ملک مسلمانوں کو مٹانے کے لئے متحد ہو رہا تھا.ایسے نازک وقت میں ابورافع اس آگ پر تیل ڈال رہا تھا جو مسلمانوں کے خلاف مشتعل تھی اور اپنے
اثر اور رسوخ اور دولت سے عرب کے مختلف قبائل کو اسلام کے خلاف ابھار رہا تھا اور اس بات کی
تیاری کر رہا تھا کہ غزوہ احزاب کی طرح عرب کے وحشی قبائل پھر متحد ہو کر مدینہ پر دھاوا بول دیں.عرب میں اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی کہ جس کے ذریعہ دادرسی چاہی جاتی بلکہ ہر قبیلہ اپنی
جگہ آزادا اور مختار تھا.پس سوائے اس کے کہ اپنی حفاظت کے لئے خود کوئی تدبیر کی جاتی اور
کوئی صورت نہیں تھی.بخاری کتاب المغازی حالات قتل ابورافع
ملاحظہ ہو حصہ دوم
: مؤطا امام مالک کتاب الجہاد
Page 831
۸۱۶
۴ یہودی لوگ پہلے سے اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان
جنگ کی حالت قائم تھی.اس وقت ایسے حالات تھے کہ اگر کھلے طور پر یہود کے خلاف فوج کشی کی جاتی تو اس سے جان اور
مال کا بہت نقصان ہوتا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ جنگ کی آگ وسیع ہوکر ملک میں عالمگیر تباہی
کا رنگ نہ پیدا کر دے.ان حالات میں صحابہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل درست اور بجا تھا اور حالت جنگ میں جب کہ ایک قوم
موت وحیات کے ماحول سے گزر رہی ہو اس قسم کی تدابیر بالکل جائز بھی جاتی ہیں اور ہر قوم اور ہر ملت
انہیں حسب ضرورت ہر زمانہ میں اختیار کرتی رہی ہے مگر افسوس ہے کہ موجودہ اخلاقی پستی کے زمانے میں
مجرم کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اس ناجائز حد تک پہنچ گیا ہے کہ ایک ظالم بھی ہیرو بن جاتا ہے اور وہ سزا
جو وہ اپنے جرموں کی وجہ سے پاتا ہے عوام کی ہمدردی کی جاذب ہونے لگتی ہے اور اس کے جرم
لوگوں کو بھول جاتے ہیں مگر اسلام کے متعلق ہمیں اعتراف ہے کہ وہ ان جھوٹے جذبات کا مذہب نہیں ہے
وہ مجرم کو مجرم قرار دیتا ہے اور اس کی سزا کو ملک اور سوسائٹی کے لئے رحمت سمجھتا ہے.وہ ایک سٹرے
ہوئے عضو کو جسم سے کاٹ دینے کی تعلیم دیتا ہے اور اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ ایک متعفن عضوا چھے
اور تندرست اعضاء کوخراب کر دے.باقی رہا طریق سزا کا سوال سو اس کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ عرب
کے اس وقت کے حالات کے ماتحت اور اس حالت جنگ کے پیش نظر جو اس وقت مسلمانوں اور یہودیوں
کے درمیان قائم تھی جو طریق اختیار کیا گیا امن عامہ کے لحاظ سے وہی بہتر اور مناسب تھا.چنانچہ ہم
اس بارے میں ایک اصولی بحث کعب بن اشرف کے معاملہ میں حصہ دوم میں درج کر چکے ہیں جس کے
اعادہ کی اس جگہ ضرورت نہیں.عبد اللہ بن عتیک کی پنڈلی کے شفا پانے کے متعلق بخاری کی روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ آیا یہ
شفا خارق عادت رنگ میں فوری طور پر وقوع میں آگئی تھی یا یہ کہ آہستہ آہستہ اپنے طبعی کورس کو پورا کر کے
ظاہر ہوئی.مؤخر الذکر صورت میں یہ ایک عام واقعہ سمجھا جائے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا
اثر صرف اس قدر متصور ہوگا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس چوٹ نے کوئی مستقل اثر نہیں چھوڑا اور کوئی
خراب نتیجہ نہیں نکلا بلکہ عبداللہ کی پنڈلی نے بالآخر اپنی اصلی اور پوری طاقت حاصل کر لی اور چوٹ کا اثر
کلیتا زائل ہو گیا لیکن اگر یہ شفا خارق عادت رنگ میں فوری طور پر وقوع میں
آئی تھی تو یقینا یہ واقعہ خدا تعالیٰ
Page 832
۸۱۷
کی تقدیر خاص کا کرشمہ تھا جو اس نے اپنے رسول کی دعا اور برکت کے نتیجہ میں ظاہر فرمایا اور اس صورت
میں اس کی تشریح اس اصولی بحث کے نیچے آئے گی جو ہم اس کتاب کے حصہ دوم میں معجزہ کے عنوان کے
تحت درج کر چکے ہیں اور جس کے اعادہ کی اس جگہ ضرورت نہیں.صرف اس قدر اشارہ کافی ہے کہ
اسلام
کی تعلیم کی رو سے خدا ہر بات پر قادر ہے اور نہ صرف قادر ہے بلکہ اپنے خاص بندوں کے ذریعہ
وہ اپنی تقدیر عام کو بدل کر اپنی خاص قدرت کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے جیسا کہ ہر نبی کے زمانہ میں اس کی
مثالیں پائی جاتی ہیں.صرف شرط یہ ہے کہ کوئی بات خدا کی سنت یا وعدہ یا صفت کے خلاف نہ ہو اور
اس میں شہود کا ایسا رنگ نہ پایا جائے جو ایمان کی غرض وغایت کو باطل کر دے.ابورافع کے قتل کے زمانہ کے متعلق روایات میں اختلاف ہے.بخاری نے زہری کی اتباع میں اسے
معتین تاریخ دینے کے بغیر مطلقاً کعب بن اشرف کے قتل کے بعد بیان کیا ہے جو بہر حال درست ہے اور
غالبا ان واقعات کو متصل کر کے اس لئے بیان کیا ہے کہ ان کی نوعیت ایک سی ہے.طبری نے اسے ۳ ہجری
میں کعب بن اشرف کے واقعہ کے بعد رکھا ہے.واقدی نے ۴ ہجری میں بیان کیا ہے.ابن ہشام نے
بروایت ابن اسحاق اسے مطلقاً غزوہ بنو قریظہ کے بعد رکھا ہے جو اواخر ۵ ہجری میں ہوا تھا اور اس طرح
اسے اوائل ۶ ہجری میں سمجھا جاسکتا ہے مگر ابن سعد نے صراحتاہ ہجری میں بیان کیا ہے اور عام مؤرخین
نے ابن سعد کی اتباع کی ہے.واللہ اعلم
مدینہ میں بارش کا قحط اور آنحضرت اسی سال ماہ رمضان میں مدینہ اور اس کے گردنواح
میں دیر تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استسقاء ہونے لگے جس پر صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تکلیف بیان کی اور درخواست کی کہ ان کے لئے بارش کی دعا فرمائی جائے اس
پر آپ صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر مصلی یعنی عیدگاہ میں تشریف لے گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر
بارش کے لئے دعا فرمائی اور اس کے بعد خدا کے فضل سے بہت جلد بارش ہوگئی.اس کے بعد اسلام میں
استسقاء کی نماز کا با قاعدہ آغاز ہو گیا.اس نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں عام نمازوں کی طرح امام
مقتدیوں کے آگے تو کھڑا ہوتا ہے مگر قولی دعا کے علاوہ جس میں انسانوں اور جانوروں کی تکلیف کا ذکر
: سيرة خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دوم
فتح الباری جلد ۲ صفحه ۴۱۵، ۴۲۵ وخمیس جلد ۲ صفحه ۱۵
۲ : طبری جلد ۳ صفحه ۱۵۵۶
Page 833
ΔΙΑ
کر کے خدا سے بارش کی التجا کی جاتی ہے امام ایک چادر کے کونے پکڑ کر اسے اپنی پیٹھ پر ڈالتا ہے اور پھر
اسے اس طرح الٹا دیتا ہے کہ چاروں کونے بدل جاتے ہیں جو گویا زبان حال سے اس بات کی استدعا
ہوتی ہے کہ خدایا ہم پر یہ تختی کے دن پوری طرح بدل جائیں اور تیری وہ رحمت جو ہر چیز کے پیچھے مخفی ہوتی
ہے تکلیف کے ظاہری پہلوؤں کو کلی طور پر دبا کر باہر آ جائے.بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور موقع پر جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ کے لئے
منبر پر چڑھے ہوئے تھے ایک صحابی نے موسم کی تختی کا ذکر کر کے عرض کیا کہ 'یا رسول اللہ ! جانور مر رہے
ہیں اور سفر کٹھن ہورہے ہیں.دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے.آپ نے اسی وقت دعا کے لئے
ہاتھ اٹھا دیئے اور بارش کے لئے بلند آواز سے دعا فرمائی.انس بن مالک جو اس روایت کے راوی ہیں اور
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدمت گار تھے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا
لیکن ابھی ہم مسجد میں ہی تھے اور جمعہ سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ ایک طرف سے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا
نمودار ہوا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ سارے آسمان پر چھا گیا.اور پھر بارش برسنے لگی اور برابر ایک ہفتہ
تک برستی رہی اور اس عرصہ میں ہم نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی ( حالانکہ اس ملک میں ایسی صورت
بہت شاذ ہوتی ہے ) پھر جب دوسرا جمعہ آیا تو ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ
یا رسول اللہ ! بارش نے تو رستے روک دیئے اور چراگاہوں کے غرقاب ہو جانے سے مویشی بھوکے
مررہے ہیں دعافرمائیں کہ اب اللہ تعالیٰ اس بارش کے سلسلہ کو روک دے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تبسم فرمایا.اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ :
اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.الخ
یعنی ” خدایا اب ہم پر اس بارش کے سلسلہ کو بند فرما اور دوسری جگہ جہاں ضرورت ہو وہاں برسا.“
انس کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی.ل : بخاری ابواب الاستسقاء باب تحویل الرداء ومشکوۃ باب نماز استسقاء
اس تبسم فرمانے میں غالباً اشارہ یہ تھا کہ انسان کسی پہلو سے بھی تسلی نہیں پاتا نیز یہ کہ اللہ کی رحمت کسی خاص چیز میں
محصور نہیں بلکہ ہر چیز رحمت بن سکتی ہے اور ہر چیز ہی عذاب کا رنگ اختیار کر سکتی ہے اس لئے ہر وقت خدا سے ڈرنا چاہئے
اور خدا سے بہر حال رحمت کو مانگتے رہنا چاہئے.ے بخاری ابواب الاستسقاء باب الاستسقاء في المسجد الجامع
Page 834
۸۱۹
اسلام میں قبولیت دعا کا مسئلہ
اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ بادل نہیں تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے دعا فرمائی اور بادل آگئے اور بارش ہونے لگی اور پھر جب بارش کی کثرت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بارش کے بند ہونے کی دعا فرمائی اور بادل چھٹ گئے اور مطلع صاف ہو گیا یعنی جب یہ باتیں
عام قانون قدرت کے ماتحت ظہور پذیر ہوتی ہیں تو پھر اس معروف و مشہور قانون قدرت کے خلاف یہ
بات کیونکر ہوگئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل نمودار ہو گئے اور پھر دعا سے ہی بادلوں نے
پھٹ کر سورج کو رستہ دے دیا ؟ سو اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہئے کہ یہ معاملہ قبولیت دعا کے مسئلہ سے
تعلق رکھتا ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر مذہب میں اور ہر زمانہ میں اس مسئلہ کو تسلیم کیا گیا ہے اور کم و بیش
ہر قوم کے مذہبی بزرگوں کی زندگی میں قبولیت دعا کی مثالیں پائی جاتی ہیں.دراصل یہ مسئلہ اپنے بیشتر
پہلوؤں میں معجزات کے مسئلہ کے ساتھ مربوط ہے جس کے متعلق ایک اصولی بحث کتاب کے حصہ دوم کے
میں گزر چکی ہے اور ہم اپنے ناظرین سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس نوٹ کے ساتھ کتاب کے
حصہ دوم کے متعلقہ اوراق بھی ضرور ملاحظہ فرمالیں.دعا کا مسئلہ مشاہدہ سے تعلق رکھتا ہے بات یہ ہے کہ ایسے امور میں استدلالی براہین کو زیادہ
دخل نہیں ہوتا بلکہ بحث کا مرکزی نقطہ یہ بات قرار پاتی
ہے کہ آیا دعا ئیں عملاً قبول ہوتی ہیں یا نہیں اور آیا کوئی بات دعا کے نتیجہ میں عملاً وقوع میں آتی ہے یا
نہیں اگر دعا کی قبولیت کا نتیجہ عملاً نظر آجائے اور ایسی صورت میں نظر آئے کہ اس میں کسی قسم کی غلط فہمی
کا امکان نہ ہوا اور سمجھدار اور معتبر اور صادق القول لوگوں کی ایک جماعت اس کی شاہد ہو اور پھر مختلف قسم
کے حالات میں ایسا مشاہدہ بار بار کے تجربہ سے پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس صورت میں کوئی عقل مند
انسان اس کے متعلق شبہ نہیں کر سکتا.جب ہم دوسرے امور میں معتبر لوگوں کی شہادت پر اپنے فیصلہ کی بنیاد
ملاحظہ ہو حصہ دوم
Page 835
۸۲۰
رکھتے ہیں اور ساری دنیا اس طریق فیصلہ کو قبول کرتی ہے حتی کہ سائنس کے جدید مشاہدات بھی خواہ ان میں
کس قدر ہی غیر متوقع اور عجیب و غریب حالات کا انکشاف ہو کم از کم ابتداء سائنسدانوں کی شہادت کے
ذریعہ ہی قبول کئے جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ سمجھ دار اور صادق القول لوگوں کی شہادت کے ہوتے
ہوئے جو مختلف قوموں اور مختلف زمانوں میں یکساں پائی جاتی ہے.دعا کی قبولیت اور معجزات و خوارق
کے وجود سے انکار کیا جائے.مسئلہ دعا اور سائنس کا مشترکہ اصول اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ سائنس کی دریافتیں تو ایسی
ہیں کہ ہر شخص جوان کا علم حاصل کرنا چاہے اور جو رستہ
اس علم کے حصول کے لئے مقرر ہے اسے اختیار کرے اور ان آلات اور ذرائع کو استعمال میں لائے جوان
امور کے معلوم کرنے یا تصدیق کرنے کے لئے ضروری ہیں تو وہ انہیں معلوم کرسکتا ہے تو اس کا جواب یہ
ہے کہ اے ہمارے بھٹکے ہوئے بھائیو! خدا تمہاری آنکھیں کھولے بعینہ یہی صورت دعا اور معجزات
اور خوارق کے معاملہ میں بھی پائی جاتی ہے.یعنی ان پر بھی یہی ازلی قانون چسپاں ہوتا ہے کہ جو شخص ان کی
حقانیت کے تجربہ کرنے کا سچا خواہش مند ہو اور اس رستہ پر گامزن ہو جو اس علم کے حصول کا رستہ ہے اور ان
ذرائع کو استعمال کرے جو اس حقیقت کی دریافت کے لئے مقرر ہیں اور اس کوشش میں وہ کسی غلط رستہ
کو اختیار کر کے بھٹک نہ جائے تو ناممکن ہے کہ وہ ان صحیح نتائج تک پہنچنے سے محروم رہے جو ہر بچے اور صحیح
طریق پر کام کرنے والے کے لئے مقدر ہیں خواہ وہ سائنس کے میدان سے تعلق رکھتا ہو یا کہ روحانیت
کے میدان سے کیونکہ دونوں کا منبع خدا کی ذات ہے اور دونوں ایک ہی ازلی حکومت کے نیچے ہیں مگر
افسوس ہے کہ دنیا کے علوم کے متعلق تو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بغیر صحیح کوشش اور صحیح جد وجہد کے
حاصل نہیں ہو سکتے اور اس لئے وہ دن رات اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے
میدان میں صد ہانا کامیاں بھی دیکھتے ہیں مگر پھر بھی ہمت نہیں ہارتے مگر روحانی میدان میں وہ صرف دل
کی خواہش یا منہ سے نکل کر اڑ جانے والے الفاظ سے تمام مراحل طے کرنا چاہتے ہیں اور جب اس طرح
ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی اور ان کا مقصود انہیں حاصل نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہو کر اس خواہش کو ہی خیر باد
کہہ دیتے ہیں اور اس مقصود کو ایک وہمی چیز قرار دینے لگ جاتے ہیں یقیناً کسی اہم مقصد کے حاصل
کرنے کا یہ طریق نہیں.قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
Page 836
۸۲۱
وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
یعنی ” جولوگ ہمارے معاملہ میں پوری پوری اور صحیح صحیح کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضروران
کے لئے اپنے رستے کھول دیتے ہیں.“
اب ناظرین خود غور کریں کیا انہوں نے اس معاملہ میں پوری پوری اور صحیح صحیح کوشش سے کام لیا
ہے؟ یعنی کیا انہوں نے کم از کم اس معاملہ میں ایسی کوشش کی ہے جو وہ دنیا میں اہم مقاصد کے لئے کیا
کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے ایسی کوشش نہیں کی اور یقینا نہیں کی تو انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی زبان اور
قلم کو بند رکھیں اور ان لوگوں کی شہادت کے متعلق حسن ظنی سے کام لیں جو اس میدان میں اپنی زندگیاں
وقف رکھتے ہیں اور جن کے حالات اس بات کے ضامن ہیں کہ وہ کم از کم مفتری یا مجنون نہیں.دعا کا مسئلہ ہستی باری تعالی در حقیقت اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا واقعی اس دنیا کا کوئی خدا ہے جس
نے اسے پیدا کیا ہے اور جو اس سارے کارخانہ عالم کو اپنے دست
کے مسئلہ کی فرع ہے قدرت سے چلا رہا ہے.اگر تو ایسا خدا ہے اور وہ دنیا کو پیدا کر کے
اپنے عرش الوہیت سے معزول نہیں ہو گیا اور نہ ہی اس کی طاقتیں معطل ہوئی ہیں تو پھر دعا کا مسئلہ عقل مند
کے نزدیک قابل اعتراض نہیں ہو سکتا.صرف سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آیا کوئی مخصوص دعا عملاً قبولیت کے
درجہ کو پہنچی ہے یا نہیں اور آیا اس کا کوئی معین نتیجہ نکلا ہے یا نہیں؟ سو یہ بات مشاہدہ کے میدان سے تعلق
رکھتی ہے جس میں استدلالی براہین کا دخل نہیں.مجھے اپنے اصل مضمون سے ہٹنا پڑتا ہے ورنہ میں
سینکڑوں مثالیں دے کر ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک نام کا بادشاہ نہیں اور نہ ہی وہ اپنے پیدا کردہ
قانون کا غلام ہے کہ اس میں کسی صورت میں بھی کوئی تبدیلی نہ کر سکے.بیشک جیسا کہ ہم آگے چل کر
بیان کریں گے وہ اپنی سنت اور وعدہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا مگر دوسری طرف وہ ایک زندہ اور متصرف
خدا ہے جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان پر یقینی نتائج مترتب کرتا ہے مگر ظاہر ہے کہ جس طرح وہ
اپنے قانون کا غلام نہیں اسی طرح وہ اپنے بندوں کا بھی غلام نہیں اور ضروری نہیں کہ ہر دعا کومنظور کرے
ل : سورة العنكبوت : ۷۰
یہ مثالیں کم و بیش ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں کیونکہ اپنی اصل کے لحاظ سے تمام مذاہب جن کی بنیاد الہام الہی پر ہے
خدا کی طرف سے ہیں اور اپنے اپنے زمانہ میں خدائی نصرت کا مشاہدہ کر چکے ہیں گواب وہ غلط رستہ پر پڑ کر اس نصرت
سے محروم ہو چکے ہوں.
Page 837
۸۲۲
بلکہ دعا کی منظوری بعض شرائط کے ساتھ مشروط ہے جنہیں ہم انشاء اللہ آگے چل کر درج کریں گے.اس اصولی نوٹ کے بعد ہم مسئلہ دعا کے متعلق اپنے ناظرین کی تنویر کے لئے چند قرآنی آیات اور
احادیث پیش کرتے ہیں تا کہ انہیں معلوم ہو سکے کہ اس بارے میں اسلامی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے سو جاننا
چاہئے کہ دعا ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی کسی کو بلانے یا پکارنے کے ہیں اور گو پکار نے اور بلانے میں
زیادہ غالب مفہوم سوال کرنے اور مانگنے کا ہوتا ہے مگر اپنے وسیع معنوں کے لحاظ سے دعا ہر رنگ کا پکارنا
شامل سمجھا جائے گا خواہ یہ پکارنا سوال یا طلب نصرت کی غرض سے ہو یا کسی اور غرض سے ہو.مثلاً اگر کوئی
شخص خدا کو محض اپنی محبت اور عبودیت کے جذبات کے اظہار کے لئے مخاطب کرتا ہے تو یہ بھی ایک نوع دعا
کی ہے خواہ اس میں کوئی پہلو سوال یا استعانت کا نہ پایا جائے مگر ان وسیع معنوں کے علاوہ دعا کے لفظ کو
اصطلاحاً ایک مخصوص اور محدود مفہوم بھی حاصل ہو گیا ہے جو سوال کرنے اور مانگنے اور طلب نصرت سے
تعلق رکھتا ہے اور اس جگہ یہی مؤخر الذکر مفہوم ہمارے مدنظر ہے.دعا کامیابی کا ایک روحانی ذریعہ ہے سب سے پہلے اسلام مسلہ دعا کے تعلق یہ تعلیم دیتا ہے
کہ دعا صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ حقیقی سوال
کا رنگ بھی رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ حسب حالات اس سوال کو قبول کرتا اور اس پر نتیجہ مترتب فرماتا ہے
اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کبھی اس روحانی ہتھیار کی طرف سے غافل نہ ہوں بلکہ اسے
ہمیشہ اپنے استعمال میں رکھیں.دراصل اسلام میں دعا کے متعلق نظریہ یہ ہے کہ جس طرح خدا نے دنیا میں
مختلف مقاصد کے حصول کے لئے مختلف ذرائع مقرر فرمائے ہیں اور خدا کا یہ منشا ہے کہ لوگ حسب حالات
ان ذرائع اور اسباب کو اختیار کریں اور ان سے فائدہ اٹھا ئیں اور دنیا میں ساری ترقی کا راز انہی اسباب
کے استعمال میں مخفی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے ان مادی اسباب کے علاوہ ایک روحانی سبب بھی مقرر
فرمایا ہے اور یہ روحانی سبب دعا ہے.اور اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اس کے بندے اپنے کاموں میں ظاہری
اور مادی ذرائع کے ساتھ ساتھ دعا یعنی روحانی ذریعہ کو بھی استعمال کریں.اور اس منشاء الہی میں دو ہری
غرض مدنظر ہے.اول: یہ کہ تا محض مادی اسباب میں گھرے رہنے کی وجہ سے لوگوں کی نظر مادیت کے ماحول میں
محصور ہوکر نہ رہ جائے اور وہ ان مادی اسباب کو ہی اپنا آخری سہارا نہ سمجھنے لگیں.بلکہ ان اسباب
کے ساتھ ساتھ ان اسباب کے پیدا کرنے والے خدا کو بھی یاد رکھیں جس کے سہارے پر یہ سارے
Page 838
۸۲۳
مادی اسباب قائم ہیں.دوم یہ کہ تا لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ جس طرح مختلف مقاصد میں کامیابی کے لئے
بعض مادی اسباب مقرر ہیں اسی طرح خدا کی ازلی تقدیر نے ایک روحانی سبب بھی مقرر کر رکھا ہے اور یہ
روحانی سبب دعا ہے جو ہمارے معاملات میں اسی طرح مؤثر ہے جس طرح کہ مادی اسباب مؤثر ہیں.البتہ جس طرح قانون قدرت کے ماتحت ہر مادی سبب کے استعمال کا ایک طریق مقرر ہے اسی طرح
روحانی سبب کے استعمال کا بھی ایک طریق مقرر ہے جسے اختیار کرنے کے بغیر وہ مؤثر نہیں ہوتا لیکن
جب اس طریق کو اختیار کر لیا جائے تو یہ روحانی سبب مادی اسباب کی نسبت بھی زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے
کیونکہ گو مادی اور روحانی اسباب ہر دو کی تہ میں خدا ہی کا ہاتھ ہے اور وہی ہر چیز کی علت العلل ہے مگر
چونکہ روحانی سبب میں گویا خدا تعالیٰ سے براہ راست اپیل ہوتی ہے اس لئے اگر اس میں صحیح طریق کو
اختیار کیا جائے تو وہ لاز م مادی اسباب کی نسبت بہت زیادہ قوی الاثر اور بہت زیادہ سریع الاثر اور
بہت زیادہ وسیع الاثر ثابت ہوتا ہے.خداد عاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے اس اصولی نوٹ کے بعد ہم مسئلہ دعا کے متعلق بعض قرآنی
آیات اور احادیث اس جگہ درج کرتے ہیں تا کہ یہ معلوم
ہو سکے کہ اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے.سوقرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخِرِيْنَ 1
یعنی ” تمہارا پروردگار تمہیں ہدایت فرماتا ہے کہ (جب بھی تمہیں کوئی ضرورت یا حاجت
پیش آیا کرے ) تم مجھے پکارا کرو.میں تمہاری پکار کوسنوں گا اور قبول کروں گا لیکن وہ لوگ
جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں (اور ان کی گردنیں مجھے پکارنے کے لئے نیچی نہیں
ہوسکتیں ) وہ عنقریب ذلیل ورسوا ہو کر آگ کے عذاب میں داخل کئے جائیں گے.“
پھر فرماتا ہے:
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِبْوَانِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ :
ل : سورۃ المومن : ۶۱
: سورة البقرة : ۱۸۷
Page 839
۸۲۴
یعنی اے رسول ! جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے پوچھیں تو تو انہیں کہہ دے کہ
میں ( تم سب کے ) قریب ہوں.میں پکارنے والے کی آواز کوسنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں
(یعنی اسے قبول کرتا ہوں ) مگر میرے بندوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری آواز پر کان دھر میں اور
مجھ پر سچا ایمان لائیں تا کہ وہ ( اپنی دعاؤں میں ) کامیابی کا منہ دیکھ سکیں.“
پھر فرماتا ہے:
اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
یعنی ”اے لوگو اپنے رب کو ہر حال میں پکارا کرو خواہ تم اضطراب اور گھبراہٹ کی حالت
میں آہ و پکار کر رہے ہو یا ضبط اور صبر کی حالت میں خاموش ہو.اور جانو کہ خدا حد اعتدال سے
بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تمہیں چاہئے کہ بعد اس کے کہ خدا نے دنیا میں اس کی اصلاح کا
سامان پیدا کر دیا ہے، فساد نہ برپا کرو اور اپنے خدا کو خوف اور طمع ہر حالت میں پکارتے رہو
( یعنی خواہ تمہیں کسی مصیبت سے رہائی پانے کی خواہش ہو یا کسی بھلائی کے حاصل کرنے کی تمنا ہو
ہر حالت میں دعا کرتے رہو ) یقیناً خدا کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے.“
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں:
إِنَّ رَبَّكُمْ حَتِى كَرِيمٌ يَسْتَحْيِ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا.یعنی ”اے مسلمانو! تمہارا رب شرمیلا اور بخشش کرنے والا آقا ہے.وہ اس بات سے
شرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے تو وہ اس کے ہاتھوں کو
خالی لوٹا دے.اللہ اللہ کیا شان دلربائی ہے.کافروں کی دعائیں مگر اس کے مقابل پر کافروں کی دعاؤں کے متعلق فرماتا ہے:
وَمَا دُعَاءُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَللٍ :
یعنی ” بے شک خدا اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے مگر اس سے یہ نہ سمجھو کہ ہر شخص کی ہر دعا
ضرور قبول ہوتی ہے بلکہ خدا کا یہ قانون ہے کہ ناشکر گزار لوگوں کی دعائیں یا کافروں کی
سورۃ الاعراف : ۵۷،۵۶
: ترندی
۳ : سورة الرعد : ۱۵
Page 840
۸۲۵
دعائیں جو وہ نیک لوگوں کے خلاف مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتیں بلکہ یونہی ادھر ادھر بھٹک کر
ضائع ہو جاتی ہیں.“
خدا اپنے وعدے اور سنت اور ایک اور جگہ فرماتا ہے:
إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ - وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ
کے خلاف دعا قبول نہیں کرتا تبدیلان
تَبْدِيلًا
یعنی اللہ تعالیٰ کسی صورت میں اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا.اور تم خدا کی سنت میں
66
کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے.“
پھر حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:
الدُّعَاءُ مُخُ الْعِبَادَةِ _
یعنی ” دعا کو عبادت میں وہ درجہ حاصل ہے جو ایک ہڈی میں گودے کو حاصل ہوتا ہے جو
گو یا ہڈی کی جان ہوتا ہے.پس جس عبادت میں دعا کا عنصر شامل نہیں وہ ایک بے جان
جسم سے بڑھ کر نہیں.مومن کی دعا خدائی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے
پھر فرماتے ہیں:
لا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ
یعنی ”لوگو! سن لو کہ دعا کو وہ طاقت حاصل ہے کہ وہ خدائی قضاء قد ر کو بھی بدل دیتی ہے
یعنی اگر عام قانون وقدر کے ماتحت کسی فرد یا قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو دعا
کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص حکم سے اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے.‘ اس جگہ وہ لوگ غور کریں
جو دعا کو محض عبادت خیال کرتے ہیں.دعا کی قبولیت کی تین امکانی صورتیں
پھر فرماتے ہیں:
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيْهَا إِثْمٌ وَ لَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى
ل : سورة آل عمران : ۱۰
: ترمذی کتاب الدعوات
سورة الاحزاب : ۶۳
ترمذی ابواب القدر
Page 841
۸۲۶
ثَلاثٍ إِمَّا يُعَجِلُ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَدْخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ
مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا
یعنی ” جب ایک مسلمان خدا سے کوئی دعا کرتا ہے تو بشرطیکہ وہ دعا کسی گناہ یا قطع رحمی
پرمشتمل نہ ہو خدا اسے تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں ضرور قبول فرمالیتا ہے
یعنی (۱) یا تو وہ اسے اسی صورت میں اسی دنیا میں قبول کر لیتا ہے اور (۲) یا اسے آخرت کے لئے
دعا کرنے والے کے واسطے ذخیرہ کر لیتا ہے اور (۳) یا (اگر اس کا قبول کرنا کسی سنت الہی یا
مصلحت الہی کے خلاف ہو تو اس کی وجہ سے دعا کرنے والے سے کسی ملتی جلتی تکلیف یا بدی
کو دور فرما دیتا ہے.قبولیت دعا کی ان تین امکانی صورتوں کے ہوتے ہوئے کون کہہ سکتا
ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ؟
دعا میں جلد بازی مہلک ہے پھر فرماتے ہیں :
إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَاحَدِكُمْ مَالَمْ يُعَجِّلُ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي وَفِي
رِوَايَةٍ مَالَمْ يَسْتَعْجِلُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِسْتِعْجَالُ قَالَ يَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ
فَلَمْ يُسْتَجَابُ لِى فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ
یعنی ” دعا میں لیے صبر و استقلال کی ضرورت ہوتی ہے اور جو انسان جلد بازی سے کام نہیں
لیتا وہ بالآخر اپنی دعا کا پھل ضرور حاصل کر لیتا ہے.ہاں اگر وہ خود تھک کر یہ کہنے لگ جائے کہ
میں نے تو بہت دعائیں کر کے دیکھ لیا ہے خدا نے میری کوئی نہیں سنی اور پھر وہ اس خیال کے
ماتحت دعا چھوڑ بیٹھے تو ایسے شخص کی دعا واقعی قبول نہیں ہوتی.“
غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی
پھر فرماتے ہیں:
اُدْعُوا اللَّهَ وَ اَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءٌ مِّنْ
قَلْبِ غَافِلٍ لَاهِ
صحیح بخاری و مسند احمد جلد ثانی صفحه ۳۹۶
ترندی
صحیح مسلم
ترندی
Page 842
۸۲۷
یعنی ” جب تم دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ خدا تمہاری دعا کو ضرور سنے گا اور یا درکھو
کہ خدا ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا ہر گز نہیں سنتا جو غافل اور بے پروا ہے.“
دعا میں معین درخواست ہونی چاہئے پھر فرماتے ہیں:
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْتَلَةَ وَلَا يَقُولَنَّ اللّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَاعْطِنِي فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ
یعنی ” جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرنے لگے تو اسے چاہئے کہ اپنے سوال پر پختگی سے
قائم ہو اور ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ خدایا اگر تو پسند کرے تو میری اس دعا کو قبول کرلے
کیونکہ خدا تو بہر حال اسی صورت میں قبول کرے گا کہ وہ اسے پسند کرے گا کیونکہ خدا سب کا
حاکم ہے اور اس پر کسی کا دباؤ نہیں.پس خواہ مخواہ مشروط یا ڈھیلے ڈھالے الفاظ کہہ کر اپنی دعا کے
زور اور اپنے دل کی توجہ کو کمزور نہیں کرنا چاہئے.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری ارشاد علم النفس کے ایک بھاری اور پختہ اصول پر مبنی ہے
کیونکہ ظاہر ہے کہ دعا کے لئے توجہ اور انہماک اور استغراق کی کیفیت ضروری ہے اور یہ کیفیت اسی صورت
میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جب دعا کرنے والا عزم اور یقین کے ساتھ ایک بات پر قائم ہو کر کسی چیز کا سوال
کرے لیکن اگر وہ اس قسم کے الفاظ کہے کہ خدایا تو اگر چاہے تو میری یہ بات مان لے تو اس صورت میں
اس کے اندر کبھی بھی وہ توجہ اور وہ استغراق کا رنگ پیدا نہیں ہو سکتا جو دعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہر حال خدا انسان کے ماتحت تو ہے نہیں کہ ہر چیز جو انسان
مانگے تو وہ ضرور اسے دے دے اور انکار کی طاقت نہ رکھتا ہو بلکہ وہ ایک حکمران خدا ہے اور اپنے مصالح
کے ماتحت قبول کرنے اور رد کرنے ہر دو کی طاقت رکھتا ہے تو پھر انسان کیوں اپنے دل میں ایک شک کی
حالت پیدا کر کے اس عزم اور توجہ اور استغراق کے مقام سے متزلزل ہو جو سوال میں کشش اور قوت جذب
پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے.خدا پر ہمیشہ نیک گمان رکھو اس اصول کی تشریح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری جگہ ان
الفاظ میں فرماتے ہیں کہ :
أَنَا عِندَظَنِّ عَبْدِي بِي
صحیح بخاری کتاب الدعوات
مسلم و بخاری
Page 843
۸۲۸
یعنی ”خدا فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اسی کے
مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں.“
یہ نکتہ بھی بے شمار کامیابیوں کی کلید ہے مگر افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف
ہیں.بہر حال دعا کے لئے عزم اور یقین کی کیفیت ضروری ہے اور عام حالات میں شک کے الفاظ میں
دعا کرنا جائز نہیں مگر یہ عدم جواز اسی صورت میں ہے کہ دعا کرنے والا عدم یقین یا عدم توجہ کی وجہ سے
ایسا طریق اختیار کرے لیکن اگر وہ خاص حالات میں توجہ اور یقین کے مقام پر قائم رہتے ہوئے پھر کسی
معاملہ میں اپنے فیصلہ کو خدا پر چھوڑ دے اور اس کی وجہ سے اس کی حالت میں بے اعتمادی یا بے توجہی یا
عدم یقین کا رنگ پیدا نہ ہو بلکہ تو کل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کا رنگ ہو تو ایسی صورت میں اس طریق پر
دعا کرنا بھی نا جائز نہیں ہوگا.دعا کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ مذکورہ بالا آیات واحادیث سے مسئلہ دعا کے متعلق
مندرجہ ذیل اصولی باتیں ثابت ہوتی ہیں.-1
لد
ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر حال میں خدا سے دعا کرتا رہے خواہ اسے خوف کی حالت در پیش
ہو یا طمع کی خواہ وہ جنگی کی حالت میں ہو یا آرام میں.خواہ وہ کسی مصیبت سے بچنا چاہتا ہو یا کسی
بھلائی کے حاصل کرنے کا آرزومند ہو.دعا ہر حالت میں ہونی چاہئے تضرع کی حالت میں بھی اور خفیہ حالت میں بھی یعنی اس وقت بھی کہ
جب انسان پر افکار کا ایسا ہجوم ہو کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکتا ہو اور وہ پھوٹ پھوٹ کر
باہر آتے ہوں اور اس وقت بھی کہ جب وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر صبر اور خاموشی کے ساتھ
اپنی التجا کو پیش کر سکتا ہو.دعا کی قبولیت کے لئے سچا ایمان اور نیکی اور طہارت اور اطاعت اور عبودیت ضروری ہیں.جولوگ خدا کی آواز پر کان دھرتے ہیں خدا بھی ان کی آواز کو زیادہ توجہ اور زیادہ محبت کے
ساتھ سنتا ہے.ناشکر لوگوں کی دعائیں جو خدا کے انعاموں پر شکر گزاری کا طریق اختیار نہیں کرتے اور نیز ان
لوگوں کی دعائیں جو خدائی نظام کے باغی ہیں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتیں بلکہ صداے صحرا کی طرح
فضا میں گونج کرختم ہو جاتی ہیں.
Page 844
۸۲۹
-1
دعا میں یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ خدائی قضا وقد رکو بھی بدل سکتی ہے یعنی اگر خدا کے عام قانون
قدرت کے ماتحت کوئی بات ہونے والی ہو اور پھر اس کا کوئی پاک بندہ اس سے اس بات کے
ٹل جانے کی دعا کرے تو خدا تعالیٰ اپنی اس عام تقدیر کو بدل کر اپنے بندے کی دعا کے مطابق
خاص تقدیر جاری کر دیتا ہے.مگر خدا کا یہ ازلی فیصلہ ہے کہ وہ اپنی کسی سنت یا وعدہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا.پس ایسی
دعا ئیں جو اس کی کسی سنت یا وعدہ کے خلاف ہوں قبول نہیں ہوتیں.اسی طرح ایسی دعا ئیں جو
گناہ یا قطع رحمی کا دروازہ کھولتی ہوں قبول نہیں ہوتیں.ے.دعا کے لئے جلد بازی سم قاتل ہے بلکہ صبر اور استقلال کے ساتھ دعا میں لگے رہنا چاہئے جولوگ
کچھ وقت دعا کر کے پھر تھک جاتے اور اس قسم کے الفاظ بولنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت
-^
-9
دعائیں کر کے دیکھ لیا خدا ہماری نہیں سنتا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں.دعا میں شک یا عدم یقین یا مایوسی کے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہئیں بلکہ یقین اور عزم کے
ساتھ یہ امید رکھتے ہوئے کہ خدا ہماری سنے گا دعا کرنی چاہئے.خدا دعا قبول کرنے یارد کرنے میں آزاد ہے.اس پر کسی کا دباؤ یا جبر نہیں.جب وہ کسی دعا کو
قبولیت کے قابل خیال کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہے اور جب قبولیت کے قابل نہیں سمجھتا تو اسے
رد کر دیتا ہے مگر بظاہر رد کرنے کی صورت میں بھی اگر دعا کرنے والا مستحق ہے تو خدا کسی اور رنگ
میں اس کی تلافی فرما دیتا ہے خواہ اسی دنیا میں خواہ آخرت میں.دعا تمام عبادتوں کی جان اور روح رواں ہے اور جو عبادت دعا سے خالی ہے وہ اس ردی اور کھوکھلی
ہڈی کی طرح ہے جو گودے سے خالی ہو.اس نوٹ کو ختم کرنے سے پہلے یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ اسلام نے نہ صرف دعا کے مسئلہ کو تشریح
اور تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اس پر خاص زور دیا ہے بلکہ مسلمانوں کو دعا کا عملی سبق دینے اور دعا کا
عادی بنانے کے لئے انسان کی ہر حرکت و سکون کے ساتھ کوئی نہ کوئی دعا مقرر کر دی ہے تا کہ اس کی کوئی
گھڑی خدا کی یاد سے خالی نہ رہے مثلاً کسی کے پیدا ہونے کسی کے وفات پانے ،مسجد میں داخل ہونے ،
مسجد سے نکلنے ،سفر میں جانے ، سفر سے واپس آنے ، سواری پر چڑھنے ،سواری سے اتر نے ، کھانا
شروع کرنے ، کھانا ختم کرنے ، بستر پر جانے ، بستر سے اٹھنے، پہاڑی پر چڑھنے ، وادی میں اتر نے،
Page 845
۸۳۰
دوستوں سے ملنے، دوستوں سے جدا ہونے شادی کرنے ، بیوی سے ملنے، نیا چاند دیکھنے، بارش کے
برسنے، بارش کے رکنے ، آندھی کے چلنے ، گھر سے نکلنے ،گھر میں داخل ہونے ، موسم کا پہلا پھل کھانے ،
بیمار کی تیمارداری کرنے کسی مسلمان کی نعش کے پاس جانے کسی مسلمان کو دفن کرنے ، غرض زندگی کے
ہر حرکت وسکون کو کسی نہ کسی دعا کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اور یہ دعا محض رسمی دعا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں
سے نکلنے والی زندہ چیز ہے جو ایک سچا مسلمان کامل یقین اور حضور قلب کے ساتھ اختیار کرتا ہے.کاش دنیا
اس عظیم الشان خزانہ کی قدر کرے.اہل خیبر کی طرف سے مزید خطرہ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کے قتل کے بعد خیبر کے
یہودیوں نے اپنی سرداری کا تاج ایک ایسے شخص کے سر پر.اور قتل اسیر بن رزام شوال ۶ ہجری رکھا جو اسلام کی عداوت میں ابورافع سے کم نہیں تھا.اس
شخص کا نام اسیر بن رزام تھا.اس ظالم نے اپنے نئے عہدہ پر فائز ہوتے ہی اس کام کی تکمیل کا تہیہ کرلیا
جسے ابورافع ادھورا چھوڑ کر مر گیا تھا.چنانچہ سب سے پہلا کام اسیر نے یہ کیا کہ تمام یہودیوں کو ایک جگہ
جمع کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سخت اشتعال انگیز تقریر کی اور کہا کہ اب تک
یہودی رؤساء نے جو تدابیر اسلام کے خلاف اختیار کی ہیں وہ درست نہیں تھیں.اب میں ایک نیا طریقہ
اختیار کروں گا اور قبائل غطفان وغیرہ کی مدد سے ایک ایسی چال چلوں
گا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )
کے گھر کی بنیاد میں نقب لگ جائے گی.اس کے بعد اس بدبخت نے نجدی قبائل غطفان وغیرہ کا
دورہ کرنا شروع کیا اور اپنی اشتعال انگیز تقریروں سے ان میں ایسی آگ لگادی کہ وہ پھر حملہ آور ہونے
کے لئے جمع ہونے لگے..جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات سے اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً اپنے ایک انصاری
صحابی عبداللہ بن رواحہ کو تین دوسرے صحابیوں کی معیت میں خیبر کی طرف روانہ فرمایا اور انہیں تاکید
فرمائی کہ خفیہ خفیہ جائیں اور سارے حالات معلوم کر کے جلد تر واپس آجا ئیں ہے چنانچہ عبد اللہ بن رواحہ
اور ان کے ساتھی گئے اور خفیہ خفیہ تمام حالات اور کوائف کا پتہ لے کر اور یہ تصدیق کر کے کہ یہ خبریں
درست ہیں واپس آگئے بلکہ عبداللہ بن رواحہ اور ان کے ساتھیوں نے ایسی ہوشیاری سے کام لیا کہ خیبر کے
ابن سعد حالات سریہ عبداللہ بن رواحہ
زرقانی جلد ۲ صفحہ ۷۰ ا حالات سریہ عبداللہ بن رواحہ
ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۶ و ابن هشام جلد ۲ صفحه ۸۲ ۸۳ ۴ : ابن سعد وزرقانی
Page 846
۸۳۱
قلعوں کے آس پاس گھوم کر اور اسیر بن رزام کی مجلس گاہوں کے پاس پہنچ کرخود اسیر اور اس کے ساتھیوں
کی زبانی یہ سن لیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ یہ تدبیریں کر رہے ہیں یا انہی دنوں میں
ایک غیر مسلم شخص خارجہ بن حُسیل اتفاقا خیبر کی طرف سے مدینہ میں آیا اور اس نے بھی عبد اللہ بن رواحہ
کی تصدیق کی اور کہا کہ میں اسیر کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے
اپنے لاؤ لشکر کو جمع کر رہا تھا یے
اس تصدیق کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کی امارت میں تمہیں صحابہ کی ایک
پارٹی خیبر کی طرف روانہ فرمائی اور گوروایات سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
پارٹی کو کیا ہدایات دے کر روانہ فرمایا تھا مگر اس گفت وشنید سے جو خیبر میں عبداللہ بن رواحہ اور اسیر بن
رزام میں ہوئی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ اسیر کو مدینہ میں بلا کر اس کے
ساتھ کوئی ایسا سمجھوتہ کیا جائے جس سے اس فتنہ انگیزی کا سلسلہ رک جائے اور ملک میں امن وامان کی
صورت پیدا ہو.اس خواہش میں آپ اس حد تک تیار تھے کہ اگر اسیر کو خیبر کے علاقہ کا امیر تک تسلیم کرنا
پڑے تو تسلیم کر لیا جائے بشرطیکہ آئندہ کے لئے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی فتنہ انگیزی سے باز آجائے.جب عبداللہ بن رواحہ کی پارٹی خیبر میں پہنچی تو سب سے پہلے انہوں نے اسیر بن رزام سے دوران
گفتگو کے لئے امن وامان کا عہد لیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت خطرہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ مسلمان
سمجھتے تھے کہ کہیں اس گفت و شنید کے درمیان ہی اسیر کی طرف سے کوئی غداری کی صورت نہ پیدا ہو جائے.اسیر نے اقرار کیا کہ ایسا نہیں ہوگا مگر ساتھ ہی اپنی شرم رکھنے کے لئے اسی قسم کا عہد عبد اللہ بن رواحہ سے
بھی لیا.مگر عبد اللہ بن رواحہ کی طرف سے اس معاملہ میں پہل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اصل خطرہ کس کی
طرف سے تھا.بہر حال اس قول و قرار کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے اُسیر سے گفتگو شروع کی جس کا مال یہ
تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ایک امن وامان کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تا کہ یہ آپس کی
جنگ رک جائے اور اس کے لئے بہترین صورت یہ ہے کہ تم خود مدینہ میں چل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے بالمشافہ بات کرو.اگر اس قسم کا معاہدہ ہو گیا تو میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ تمہارے ساتھ احسان
ل: زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۷۰
زرقانی
ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۸۳٬۸۲ و ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۷ وسیرت حلبیہ جلد ۳ صفحه ۲۰۳
: ابن سعد جلد ۳ صفحه ۶۷
Page 847
۸۳۲
کا معاملہ کریں گے اور ممکن ہے کہ تمہیں خیبر کا باقاعدہ رئیس تسلیم کر لیا جائے یا اُسیر کو جو سخت جاہ طلب تھا
یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی اور نیت مخفی ہو یہ تجویز پسند آئی اور کم از کم اس نے یہ ظاہر کیا کہ
مجھے یہ تجویز پسند ہے مگر ساتھ ہی اس نے خیبر کے یہودی عمائد کو جمع کر کے ان سے مشورہ مانگا کہ مسلمانوں
کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی ہے اس کے متعلق کیا کیا جائے.یہود نے جو اسلام کے خلاف عامیانہ
عداوت میں اندھے ہورہے تھے عام طور پر اس تجویز کی مخالفت کی اور اُسیر کو اس ارادے سے باز رکھنے
کی غرض سے کہا کہ ہمیں امید نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہیں خیبر کا امیر تسلیم کریں مگر اسیر جو حالات
سے زیادہ واقف تھا اپنی بات پر قائم رہا اور کہنے لگا " تم نہیں جانتے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) اس
جنگ سے تنگ آیا ہوا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ جس طرح ہو اس لڑائی کا سلسلہ رک جائے ہے
الغرض اسیر بن رزام عبد اللہ بن رواحہ کی پارٹی کے ساتھ مدینہ چلنے کے لئے تیار ہو گیا اور عبداللہ بن
رواحہ کی طرح خود اس نے بھی تمہیں یہودی اپنے ساتھ لے لئے.جب یہ دونوں پارٹیاں خیبر سے نکل کر
ایک مقام قر قرہ میں پہنچیں جو خیبر سے چھ میل کے فاصلہ پر تھا یا تو اسیر کی نیت بدل گئی یا اگر اس کی نیت
پہلے سے خراب تھی تو یوں سمجھنا چاہئے کہ اس کے اظہار کا وقت آ گیا.چنانچہ اس نے باتیں کرتے کرتے
بڑی ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں کی پارٹی کے ایک معزز فرد عبداللہ بن انیس انصاری کی تلوار کی طرف
ہاتھ بڑھایا.عبداللہ فوراً تاڑ گئے کہ اس بد بخت کے تیور بدلے ہوئے ہیں.چنانچہ انہوں نے جھٹ اپنی
اونٹنی کو ایڑ لگا کر اسے آگے کر لیا اور پھر اُسیر کی طرف گھوم کر آواز دی کہ اے دشمن خدا کیا تم ہمارے ساتھ
غداری کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن انیس نے دو دفعہ یہ الفاظ دہرائے.مگر اسیر نے کوئی جواب نہیں دیا نے
اور نہ ہی اس نے اپنی کوئی بریت کی بلکہ وہ سامنے سے جنگ کے لئے تیار تھا.یہ غالباً یہودیوں میں پہلے
سے مقرر شدہ اشارہ تھا کہ ایسا موقع آئے تو سب مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں.چنانچہ اسی جگہ عین راستہ
میں مسلمانوں اور یہودیوں میں تلوار چل گئی.اور گو دونوں پارٹیاں تعداد میں برابر تھیں اور یہودی لوگ
پہلے سے ذہنی طور پر تیار تھے اور مسلمان بالکل بے ارادہ تھے مگر خدا کا ایسا فضل ہوا کہ بعض مسلمان
زخمی تو بیشک ہوئے مگر ان میں سے کسی جان کا نقصان نہیں ہوا لیکن دوسری طرف سارے یہودی اپنی
: ابن سعد وابن ہشام وزرقانی
: ابن سعد
سيرة حلبیہ جلد ۳ حالات سریہ عبداللہ بن رواحہ
ابن ہشام
۵ : ابن سعد وابن ہشام
ابن سعد
Page 848
۸۳۳
غداری کا مزا چکھتے ہوئے خاک میں مل گئے لے
جب صحابہ کی یہ پارٹی مدینہ میں واپس پہنچی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے اطلاع ہوئی
تو آپ نے مسلمانوں کے صحیح سلامت بچ جانے پر خدا کا شکر کیا اور فرمایا:
قَدْنَجَاكُمُ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
66
شکر کرو کہ خدا نے تمہیں اس ظالم پارٹی سے نجات دی.“
اس واقعہ کے متعلق بعض مسیحی مؤرخین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ گویا عبداللہ بن رواحہ کی پارٹی اُسیر
وغیرہ کو خیبر سے اسی نیت سے نکال کر لائی تھی کہ رستہ میں موقع پا کر انہیں
قتل کر دیا جائے مگر یہ اعتراض
مغربی سینہ زوری کے ایک ناگوار مظاہرہ کے سوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا
ہے تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مسلمان اس نیت سے وہاں گئے تھے بلکہ غور کیا جاوے تو
قطع نظر دوسرے شواہد کے صرف عبد اللہ بن انیس کے یہ الفاظ ہی کہ اے دشمن خدا! کیا غداری کی نیت
ہے؟ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ شکر کرو کہ خدا نے تمہیں اس ظالم پارٹی سے
نجات دی.اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ مسلمانوں کی نیت بالکل صاف اور پر امن تھی
اور جو کچھ ہوا وہ محض اس غداری کا نتیجہ تھا جو یہودی لوگ حسب عادت مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہتے
تھے مگر جسے خدا نے اپنے فضل سے خود انہی پر الٹا دیا.وو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی غزوہ احزاب کی ذلت بھری ناکامی کی یاد نے
قریش مکہ کے تن بدن میں آگ لگا رکھی تھی اور طبعاً
سازش اور سریہ عمرو بن امیہ شوال ۶ ہجری قلبی آگ زیادہ تر ابوسفیان کے حصہ میں آئی تھی
جو مکہ کا رئیس تھا اور احزاب کی مہم میں خاص طور پر ذلت کی مار کھا چکا تھا.کچھ عرصہ تک ابوسفیان اس آگ
میں اندر ہی اندر جلتا رہا مگر بالآخر معاملہ اس کی برداشت سے نکل گیا اور اس آگ کے مخفی شعلے باہر آنے
شروع ہو گئے.طبعا کفار کی سب سے زیادہ عداوت بلکہ در حقیقت اصل عداوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات کے ساتھ تھی.اس لئے اب ابوسفیان اس خیال میں پڑ گیا کہ جب ظاہری تدبیروں اور حیلوں
کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کیوں
کسی مخفی تدبیر سے
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا خاتمہ نہ کر دیا جائے.وہ جانتا تھا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کوئی خاص پہرہ نہیں رہتا بلکہ بعض اوقات آپ بالکل بے حفاظتی کی
ابن ہشام وابن سعد
ابن سعد
Page 849
۸۳۴
حالت میں ادھر ادھر آتے جاتے.شہر کے گلی کوچوں میں پھرتے.مسجد میں روازنہ کم از کم پانچ وقت
نمازوں کے لئے تشریف لاتے اور سفروں میں بالکل بے تکلفانہ اور آزا د طور پر رہتے ہیں.اس سے
زیادہ اچھا موقع کسی کرایہ دار قاتل کے لئے کیا ہو سکتا تھا؟ یہ خیال آنا تھا کہ ابوسفیان نے اندر ہی اندر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز پختہ کرنی شروع کر دی.جب وہ پورے عزم کے ساتھ اس ارادے پر جم گیا تو اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے مطلب
کے چند قریشی نو جوانوں سے کہا کہ ” کیا تم میں سے کوئی ایسا جوانمرد نہیں جو مدینہ میں جا کر خفیہ خفیہ
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا کام تمام کر دے؟ تم جانتے ہو کہ محمد کھلے طور پر مدینہ کی گلی کوچوں میں پھرتا
ہے.ان نوجوانوں نے اس خیال کو سنا اور لے اڑے.ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک بدوی
نوجوان ابوسفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے آپ کی تجویز سنی ہے اور میں اس کے لئے حاضر ہوں.میں ایک مضبوط دل والا اور پختہ کار انسان ہوں جس کی گرفت سخت اور حملہ فوری ہوتا ہے.اگر آپ مجھے
اس کام کے لئے مقرر کر کے میری مدد کریں تو میں محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کو قتل کرنے کی غرض سے جانے
کے لئے تیار ہوں.اور میرے پاس ایک ایسا خنجر ہے جو شکاری گدھ کے مخفی پروں کی طرح رہے گا.سو میں
محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) پر حملہ کروں گا اور پھر بھاگ کر کسی قافلہ میں مل جاؤں گا اور مسلمان مجھے پکڑ نہیں
سکیں گے اور میں مدینہ کے رستے کا بھی خوب ماہر ہوں.ابوسفیان نے کہا.”بس بس تم ہمارے مطلب
کے آدمی ہو.اس کے بعد ابوسفیان نے اسے ایک تیز رو اونٹنی اور زاد راہ وغیرہ دے کر رخصت کیا اور
تاکید کی کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا ہے
مکہ سے رخصت ہو کر یہ شخص دن کو چھپتا ہوا اور رات کو سفر کرتا ہوامد بینہ کی طرف روانہ ہوا اور چھٹے
دن مدینہ پہنچ گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لیتے ہوئے سیدھا قبیلہ بنی عبدالاشہل کی مسجد میں
پہنچا جہاں آپ اس وقت تشریف لے گئے ہوئے تھے.چونکہ ان ایام میں نئے سے نئے آدمی مدینہ میں
آتے رہتے تھے اس لئے کسی مسلمان کو اس کے متعلق شبہ نہیں ہوا مگر جو نہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے اپنی طرف آتے دیکھا آپ نے فرمایا یہ شخص کسی بری نیت سے آیا ہے.وہ یہ الفاظ سن کر اور بھی تیزی
کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا مگر ایک انصاری رئیس اُسید بن حضیر فور لپک کر اس کے ساتھ لپٹ گئے اور
اس جدو جہد میں ان کا ہاتھ اس کی چھپی ہوئی خنجر پر جاپڑا جس پر وہ گھبرا کر بولا.” میرا خون میرا خون.“
ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۸
Page 850
۸۳۵
جب اسے مغلوب کر لیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور
کس ارادے سے آئے ہو؟ اس نے کہا میری جان بخشی کی جائے تو میں بتا دوں گا.آپ نے فرمایا
ہاں اگر تم ساری بات سچ سچ بتا دو تو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا.جس پر اس نے سارا قصہ من وعن
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ ابوسفیان نے اس سے اس اس قدر
انعام کا وعدہ کیا تھا.اس کے بعد یہ شخص چند دن تک مدینہ میں ٹھہرا اور پھر اپنی خوشی سے مسلمان ہوکر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو گیا.ابوسفیان کی اس خونی سازش نے اس بات کو آگے سے بھی زیادہ ضروری کر دیا کہ مکہ والوں کے
ارادے اور نیت سے آگاہی رکھی جائے.چنانچہ آپ نے اپنے دوصحابی عمرو بن امیہ ضمری اور سلمہ بن اسلم
کو مکہ کی طرف روانہ فرمایا اور ابوسفیان کی اس سازش قتل اور اس کی سابقہ خون آشام کارروائیوں کو دیکھتے
ہوئے انہیں اجازت دی کہ اگر موقع پائیں تو بیشک اسلام کے اس حربی دشمن کا خاتمہ کر دیں.مگر جب
امیہ اور ان کا ساتھی مکہ میں پہنچے تو قریش ہوشیار ہو گئے اور یہ دوصحابی اپنی جان بچا کر مدینہ کی طرف
واپس لوٹ آئے.راستہ میں انہیں قریش کے دو جاسوس مل گئے جنہیں رؤساء قریش نے مسلمانوں کی
حرکات وسکنات کا پتہ لینے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا
اور کوئی تعجب نہیں کہ یہ تدبیر بھی قریش کی کسی اور خونی سازش کا پیش خیمہ ہومگر خدا کا فضل ہوا کہ امیہ اور سلمہ کو
ان کی جاسوسی کا پتہ چل گیا جس پر انہوں نے ان جاسوسوں پر حملہ کر کے انہیں قید کر لینا چاہا مگر انہوں نے
سامنے سے مقابلہ کیا.چنانچہ اس لڑائی میں ایک جاسوس تو مارا گیا اور دوسرے کو قید کر کے وہ اپنے ساتھ
مدینہ میں واپس لے آئے.ہے
اس سریہ کی تاریخ کے متعلق مؤرخین میں اختلاف ہے.ابن ہشام اور طبری اسے ۴ھ میں بیان
کرتے ہیں مگر ابن سعد نے اسے ۶ھ میں لکھا ہے اور علامہ قسطلانی اور زرقانی نے ابن سعد کی روایت کو
ترجیح دی ہے لہذا میں نے بھی اسے ۶ھ میں بیان کیا ہے واللہ اعلم.ابن سعد کی روایت کے مفہوم کی تائید
بیہقی نے بھی کی ہے.مگر اس میں اس واقعہ کے زمانہ کا پتہ نہیں چلتا.ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۸ وزرقانی جلد ۲ حالات سریہ عمرو بن امیہ ضمری
ابن سعد جلد ۲ صفحه ۶۸ وزرقانی جلد ۲ صفحه ۱۷۸ وابن ہشام جلد ۳ صفحه ۹۰،۸۹ و طبری جلد ۳ صفحه ۱۴۳۷ تا صفحه ۱۴۴۱
۳ : زرقانی جلد ۲ صفحہ ۱۷۷
Page 851
۸۳۶
قبائل مشکل وعرینہ کی غداری اور مسلمانوں کے لئے یہ دن بہت خطرناک تھے کیونکہ قریش
اور یہود کی انگیخت سے سارا ملک ان کی عداوت کی آگ سے
اس کا ہولناک انجام شوال ۶ ہجری شعلہ زن ہور ہا تھا.اور اپنی جدید پالیسی کے ماتحت انہوں
نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ مدینہ پر باقاعدہ حملہ کرنے کی بجائے در پردہ طریقوں سے نقصان پہنچایا جائے
اور چونکہ دھوکا دہی اور غداری عرب کے وحشی قبائل کے اخلاق کا حصہ تھی اس لئے وہ ہر جائز و نا جائز طریق
سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے.چنانچہ جس واقعہ کا ذکر ہم اب کرنے لگے ہیں وہ اسی
ناپاک سلسلہ کی ایک کڑی تھی جو ایک ہولناک رنگ میں اپنے انجام کو پہنچی.تفصیل اس کی یہ ہے کہ شوال
۶ ہجری میں قبیلہ شکل اور عُرینہ کے چند آدمی " جو تعداد میں آٹھ تھے.مدینہ میں آئے اور اسلام کے
ساتھ محبت اور موانست کا اظہار کر کے مسلمان ہو گئے.کچھ عرصہ کے قیام کے بعد انہیں مدینہ کی آب و ہوا
میں معدہ اور تلی وغیرہ کی جو کچھ شکایت پیدا ہوئی تو وہ اسے بہانہ بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور اپنی تکلیف بیان کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ! ہم جنگلی لوگ ہیں اور جانوروں کے ساتھ رہنے
میں عمر گزاری ہے اور شہری زندگی کے عادی نہیں اس لئے بیمار ہو گئے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہاں مدینہ میں تکلیف ہے تو مدینہ سے باہر جہاں ہمارے مویشی رہتے ہیں وہاں
چلے جاؤ اور اونٹوں کا دودھ وغیرہ پیتے رہو.اچھے ہو جاؤ گے.اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے
خود کہا کہ یارسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم مدینہ سے باہر جہاں آپ کے مویشی رہتے ہیں
وہاں چلے جاتے ہیں جس کی آپ نے اجازت دے دی بہر حال وہ آنحضرت سے اجازت لے کر مدینہ
سے باہر اس چراگاہ میں چلے گئے جہاں مسلمانوں کے اونٹ رہتے تھے.جب ان بدبختوں نے یہاں اپنا ڈیرا جمالیا اور آگے پیچھے نظر ڈال کر سارے حالات معلوم کر لئے
اور کھلی ہوا میں رہ کر اور اونٹوں کا دودھ پی کر خوب موٹے تازے ہو گئے تو ایک دن اچانک اونٹوں کے
رکھوالوں پر حملہ کر کے انہیں مار دیا اور مارا بھی اس بے دردی سے کہ پہلے تو جانوروں کی طرح ذبح کیا اور
پھر جب ابھی کچھ جان باقی تھی تو ان کی زبانوں میں صحرا کے تیز کانٹے چھوئے تا کہ جب وہ منہ سے
ابن سعد
مسلم کتاب القسامة
ابو عوانه بروایت زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۷۳
: بخاری کتاب المغازی
بخاری کتاب المغازی و کتاب المحاربين
Page 852
۸۳۷
کوئی آواز نکالیں یا پیاس کی وجہ سے تڑپیں تو یہ کانٹے ان کی تکلیف کو اور بھی بڑھا دیں لیے اور پھر ان
ظالموں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ گرم سلائیاں لے کر ان نیم مردہ مسلمانوں کی آنکھوں میں پھیریں نے
اور اس طرح یہ بے گناہ مسلمان کھلے میدان میں تڑپ تڑپ کر جان بحق ہو گئے.ان میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی خادم بھی تھا جس کا نام سیسار تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں
کے چرانے پر مقرر تھا.کے
جب یہ درندے اس وحشیانہ رنگ میں مسلمانوں کا کام تمام کر چکے تو پھر سارے اونٹوں کو اکٹھا کر کے
انہیں ہنکالے گئے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حالات ایک رکھوالے نے پہنچائے جو اتفاق سے بیچ
کر نکل آیا تھا جس پر آپ نے فورا ہیں صحابہ کی ایک پارٹی تیار کر کے ان کے پیچھے بھجوادی اور گو یہ لوگ کچھ
فاصلہ طے کر چکے تھے مگر خدا کا یہ فضل ہوا کہ مسلمانوں نے پھرتی کے ساتھ پیچھا کر کے انہیں جا پکڑا اور
رسیوں سے باندھ کر واپس لے آئے.اس وقت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکام نازل نہیں
ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی حرکت کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہئے چنانچہ آپ نے
اپنے قدیم اصول کے ماتحت کہ جب تک اسلام میں کوئی نیا حکم نازل نہ ہو اہل کتاب کے طریق پر چلنا
چاہئے یا موسوی شریعت کے مطابق ھے حکم دیا کہ جس طرح ان ظالموں نے مسلمان رکھوالوں کے ساتھ
سلوک کیا ہے اسی طرح قصاصی اور جوابی صورت میں ان کے ساتھ کیا جائے تا کہ یہ سزا دوسروں کے لئے
عبرت ہو.چنانچہ خفیف تغیر کے ساتھ اسی رنگ میں مدینہ سے باہر کھلے میدان میں ان لوگوں کو موت کے
گھاٹ اتار دیا گیا.مگر اسلام کے لئے خدا نے دوسری تعلیم مقدر کر رکھی تھی چنانچہ آئندہ جوابی اور قصاصی
صورت میں بھی مثلہ کی سز منع کر دی گئی یعنی اس بات
کو نا جائز قرار دیا گیا کہ کسی رنگ میں مقتول کے جسم کو
بگاڑا جائے یا انتقامی رنگ میں اعضاء کوٹکڑے ٹکڑے کیا جائے وغیر ذالک.اس واقعہ کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بہر حال اس معاملہ میں ظلم کی ابتدا
ل ابن ہشام وابن سعد
مسلم کتاب القسامة باب حکم المحاربین اور ترمذی کتاب الطہارة ما جاء فی بول ما يوكل لحمه
: ابن ہشام
بخاری کتاب اللباس باب الفرق
ه خروج ۲۱ و ا حبار ۲۴ واستثناء ۱۹
: بخاری کتاب المغازی قصه مشکل وعرینه وابن سعد حالات سر یه کرز بن جابر وسر ولیم میور صفحه۳۵۰
Page 853
۸۳۸
کفار کی طرف سے تھی جنہوں نے بغیر کسی جائز وجہ کے محض اسلام کی عداوت میں بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ
اس قسم کا ظالمانہ اور وحشیانہ سلوک کیا اور جو کچھ ان کی سزا میں کیا گیا وہ محض قصاصی اور جوابی تھا اور تھا
بھی ایسے حالات میں جب کہ اسلام کے خلاف سارا ملک دشمنی اور عداوت کی آگ سے بھڑک رہا تھا
اور پھر یہ فیصلہ بھی موسوی شریعت کے مطابق کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی اسلام نے اسے برقرار نہیں رکھا اور
آئندہ کے لئے ایسے طریق سے منع کر دیا.ان حالات میں کوئی عقل مند اس پر اعتراض نہیں کر سکتا.اس
موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ لوگ شروع سے ہی بری نیت کے ساتھ مدینہ میں آئے تھے اور غالبا اپنے
قبیلہ کے سکھائے ہوئے تھے کہ تا مسلمانوں میں رہ کر انہیں نقصان پہنچائیں اور ممکن ہے کہ خود آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ان کا کوئی برا ارادہ ہو مگر جب مدینہ میں رہ کر انہیں کوئی موقع نہیں ملا
تو انہوں نے یہ تجویز کی کہ مدینہ سے باہر نکل کر کارروائی کی جاوے.ان کی اس نیت کا اس سے بھی پتہ لگتا
ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چرواہوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ خالی چوروں اور لیٹروں والا سلوک نہیں
تھا بلکہ سراسر منتقمانہ رنگ رکھتا تھا.اگر وہ ابتدا میں سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے اور بعد میں
اونٹ دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی تو اس صورت میں ہونا یہ چاہئے تھا کہ وہ اونٹ لے کر بھاگ جاتے اور
اگر کوئی رکھوالا روک بنتا تو زیادہ سے زیادہ اسے مار کر نکل جاتے مگر جس رنگ میں انہوں نے مسلمان
چرواہوں
کو قتل کیا اور اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال کر قتل کے سفا کا نہ فعل کولمبا کیا اور عذاب دے کر مارا اس
سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا یہ فعل اتفاقی لالچ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ سراسر معاندانہ رنگ رکھتا تھا اور دلی کینہ
اور لمبے بغض کا نتیجہ تھا اور ان کے اس ظالمانہ فعل کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا
وہ محض قصاصی اور جوابی تھا جو اسلامی احکام کے نزول سے پہلے موسوی شریعت کے مطابق کیا گیا لیکن
اس کے بعد جلد ہی اسلامی احکام نازل ہو گئے اور اس قسم کی تعذیب انتقامی رنگ میں بھی ناجائز قراردے
دی گئی چنا نچہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں :
اَنَّ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُ غُلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ
یعنی اس واقعہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم احسان اور حسن سلوک کی تاکید فرمایا
66
کرتے تھے اور ہر حال میں دشمنوں کے جسموں کے مثلہ کرنے سے منع فرماتے تھے.“
بعض مغربی محققین نے جن میں میور صاحب بھی شامل ہیں.اس واقعہ کے حالات کا ذکر کرتے
بخاری کتاب المغازی باب قصه عکل
میور صفحه ۳۵۰
Page 854
۸۳۹
ہوئے حسب عادت اعتراض کیا ہے کہ جس رنگ میں ان قاتل ڈاکوؤں کو قتل کیا گیا وہ ظالمانہ اور وحشیانہ
تھا لیکن اگر سارے حالات کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو اس معاملہ میں اسلام کا دامن بالکل پاک نظر
آتا ہے کیونکہ در اصل یہ فیصلہ اسلام کا نہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ کا تھا یا جن کی شریعت کو حضرت
مسیح ناصری
نے منسوخ نہیں کیا بلکہ برقرار رکھا.ہاں اگر ہمارے معترضین کے پیش نظر حضرت
مسیح کا یہ قول ہے کہ ایک
گال پر طمانچہ کھا کر دوسرا گال بھی سامنے کردو اور اگر کوئی شخص تمہارا کر نہ لینا چاہے تو اسے اپنا چونہ بھی دے
دو اور اگر کوئی تمہیں ایک کوس بیگار لے جانا چاہے تو دو کوس چلے جاؤ تو بے شک ہمارے معترضین کو اس
اعتراض کا حق ہے.مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعلیم کسی عقل مند کے نزدیک قابل عمل ہے اور کیا آج تک ان
ساڑھے انیس سو سالوں میں کسی مسیح مرد یا عورت یا کسی مسیحی جماعت یا حکومت نے اس تعلیم پر عمل کیا
ہے؟ منبروں پر چڑھ کر وعظ کرنے کے لئے بیشک یہ ایک عمدہ تعلیم ہے مگر عملی دنیا میں اس تعلیم کو کوئی بھی
وزن حاصل نہیں اور نہ کوئی عقل مند اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہوسکتا ہے.اس صورت میں اس قسم کے
جذباتی کھلونے سامنے رکھ کر مسلمانوں کو اعتراض کا نشانہ بنانا خود اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے.ہاں
حضرت موسی کی تعلیم کو سامنے رکھ کر دیکھو جو بخلاف حضرت مسیح ایک سچے مقئن تھے اور قانون کی حقیقت کو
اچھی طرح سمجھتے تھے یا مسیحیوں کے قول کو نہیں بلکہ ان کے عملی کارناموں کی روشنی میں حالات کا امتحان کرو
تو پھر حقیقت واضح ہوتی ہے کہ عملی میدان میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے
وہی کرتا ہے اور اس کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت الگ الگ نہیں ہیں اور اس کے قول و فعل ہر دو
اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ کوئی عقل مند غیر متعصب انسان ان پر اعتراض نہیں کر سکتا بلکہ دل سے اس کی
تعریف نکلتی ہے.نہ تو وہ موسوی شریعت کی طرح یہ کہتا ہے کہ ہر حالت میں انتقام لو اور بلا امتیاز حالات
قصاص کا ئبر چلاتے جاؤ اور نہ وہ مسیحی تعلیم کے مطابق یہ ہدایت کرتا ہے کہ کسی حالت میں بھی سزا نہ دو بلکہ
اگر مجرم کوئی جرم کرے تو اس کے جرم کے منشا کو اپنی طرف سے مدد کر کے اور بھی مضبوط کر دو بلکہ اسلام
افراط و تفریط کے رستے کو چھوڑ کر وہ وسطی تعلیم دیتا ہے جو دنیا میں حقیقی امن کی بنیاد ہے اور وہ یہ کہ :
جَزْؤُا سَيِّئَةِ سَيْئَةٌ مِثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ
خروج باب ۲۱ آیت ۲۳ تا ۲۵ و احبار باب ۲۴ آیت ۱۹ تا ۲۱ واستثناء باب ۱۹ آیت ۲۱
: متی باب ۵ آیت ۱۷ تا ۱۹
قرآن شریف سورة الشورى : ۴۱
: متی باب ۵ آیت ۳۸ تا ۴۱
Page 855
۸۴۰
یعنی ” ہر بدی کی سزا اس کے مناسب حال اور اس کی شدت کے مطابق ہونی چاہئے لیکن اگر حالات
ایسے ہوں کہ معاف کرنے یا نرمی کرنے سے اصلاح کی امید ہو تو پھر معاف کرنا یا نرمی کرنا بہتر ہے اور
ایسا شخص خدا کے نزدیک نیک اجر کا مستحق ہوگا یہ وہ تعلیم ہے جو اسلام نے اس بارے میں دی اور کوئی
عقل مند اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایک بہترین تعلیم ہے جس میں انسانی ضروریات کے تمام
پہلوؤں کو مدنظر رکھا گیا ہے اور سزا کی صورت میں بھی اسلام نے یہ قید لگا دی ہے کہ وہ مناسب حد سے
آگے نہ گزرے اور مثلہ وغیرہ کے وحشیانہ افعال کو یک قلم بند کر دیا گیا.اس کے مقابل پر مسیحی لوگ
باوجود حضرت مسیح ناصری کی اس نمائشی تعلیم کے جو عملی نمونہ دشمنوں کے ساتھ سلوک کا دکھاتے رہے ہیں اور
جنگوں میں جن افعال کے مرتکب ہوتے رہے ہیں وہ تاریخ عالم کا ایک کھلا ہوا ورق ہے جس کے اعادہ کی
اس جگہ ضرورت نہیں.
Page 856
۸۴۱
صلح حدیبیہ اور اس کے عظیم الشان نتائج
ذ وقعده ۶ ہجری
صلح حدیبیہ کی اہمیت اب ہم اسلامی تاریخ کے اس حصہ میں داخل ہونے لگے ہیں جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے دوسرے دور میں خاص اہمیت رکھتا ہے.میری مراد صلح حدیبیہ سے ہے جس کے نتیجہ میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ وجدال کا سلسلہ
بند ہو کر اسلام کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور دنیا کو اس بات کے اندازہ کرنے کا موقع میسر
آیا کہ اسلام کی اصل طاقت صلح میں ہے نہ کہ جنگ میں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی زندگی میں بظاہر
جنگ نہیں تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رؤساء قریش کی حکومت کے ماتحت زندگی
گزارتے تھے مگر قریش کی یہ حکومت جنگ سے بھی بڑھ کر مظالم ومصائب کا منظر پیش کرتی تھی کیونکہ
قریش کی ساری طاقت اسلام کو مٹانے میں خرچ ہورہی تھی.اس کے بعد مدنی زندگی کا دور آیا تو اس کے
ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہو گیا اور بے چارے مسلمان ایک مصیبت میں سے نکل کر دوسری مصیبت اور
بعض لحاظ سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گئے ، اس لئے حقیقتا آج تک اسلام کو اپنی صلح کی طاقت کے اظہار
کا موقع ہی نہیں ملا تھا، لیکن صلح حدیبیہ نے جس کا اب ہم ذکر شروع کرنے لگے ہیں یہ موقع میسر کرا دیا
اور دنیا جانتی ہے کہ اس امتحان میں اسلام نے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت کر دی کہ اس کی صلح کی
طاقت اس کی جنگ کی طاقت سے بدر جہا بہتر اور بدر جہا افضل ہے.الغرض وہ تاریخی واقعہ جس کا ہم
اب ذکر کر نے لگے ہیں ایک نہایت اہم واقعہ ہے.اور ہم اپنے ناظرین سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ اس
واقعہ کے حالات کو نظر غور سے مطالعہ فرمائیں.مطابق فروری مارچ ۶۲۸ء
Page 857
۸۴۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور سفر حدیبیہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے
مدینہ میں تشریف لائے تو اس کے جلد بعد ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی طرف سے
بدل کر بیت اللہ کی طرف پھیر دیا تھا اور اس تحویل قبلہ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ اپنی توجہ کو مکہ کی طرف لگائے رکھیں اور اس بات
کو کبھی نہ بھولیں کہ مکہ اسلام کا مذہبی
مرکز ہے جو جتنی جلدی بھی ممکن ہو مسلمانوں کے قبضہ میں آ جانا چاہئے.ان احکام کی وجہ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مکہ کی طرف خیال لگارہتا تھا اور پھر وطن ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو اور آپ کے
ساتھ کے مہاجرین کو مکہ کے ساتھ طبعا خاص محبت تھی.اس پر اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں جن کا ہم ذکر
کر رہے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا
طواف کر رہے ہیں.تے اس وقت ذوقعدہ کا مہینہ قریب تھا جو زمانہ جاہلیت میں بھی ان چار مبارک مہینوں
میں سے سمجھا جاتا تھا جن میں ہر قسم کا جنگ وجدال منع تھا.گویا ایک طرف آپ نے یہ خواب دیکھی
اور دوسری طرف یہ وقت بھی ایسا تھا کہ جب عرب کے طول و عرض میں جنگ کا سلسلہ رک کر امن وامان
ہو جاتا تھا اور گو یہ حج کے دن نہیں تھے اور ابھی تک اسلام میں حج با قاعدہ طور پر مقرر بھی نہیں ہوا تھا لیکن
خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت ہو سکتا تھا اس لئے آپ نے اس خواب دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ سے تحریک
فرمائی کہ وہ عمرہ کے واسطے تیاری کرلیں.عمرہ گویا ایک چھوٹی قسم کا حج تھا جس میں حج کے بعض مناسک کو
ترک کر کے صرف بیت اللہ کے طواف اور قربانی پر اکتفا کی جاتی تھی اور بخلاف حج کے اس کے لئے سال
کا کوئی خاص حصہ بھی معین نہیں تھا بلکہ یہ عبادت ہر موسم میں ادا کی جاسکتی تھی.اس موقع پر آپ نے صحابہ
میں یہ بھی اعلان
فرمایا کہ چونکہ اس سفر میں کسی قسم کا جنگی مقابلہ مقصود نہیں ہے بلکہ محض ایک پر امن دینی
عبادت کا بجالانا مقصود ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ اس سفر میں اپنے ہتھیار ساتھ نہ لیں البتہ عرب
کے دستور کے مطابق صرف اپنی تلواروں کو نیاموں کے اندر بند کر کے مسافرانہ طریق پر اپنے ساتھ رکھا
جا سکتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے مدینہ کے گردونواح کے بدوی لوگوں میں بھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ
تھے یہ تحریک فرمائی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو کر عمرہ کی عبادت بجالائیں مگر افسوس ہے کہ ایک
ا: سورة البقرة : ۱۴۹ تا ۱۵۱
: سورة الفتح : ۲۸ و ابن جریر جلد ۲۶ صفحه ۶۸ وزرقانی جلد ۲ صفحه ۱۷۹ و تاریخ خمیس حالات حدیبیہ
Page 858
۸۴۳
نہایت قلیل یعنی برائے نام تعداد کے سوا ان مسلمان کہلانے والے کمزور ایمان بدوی لوگوں نے جو
مدینہ کے آس پاس آباد تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے احتراز کیا کیونکہ ان کا خیال تھا
کہ خواہ مسلمانوں کی نیت عمرہ کے سوا کچھ نہیں مگر قریش بہر حال مسلمانوں کو روکیں گے اور اس طرح مقابلہ
کی صورت پیدا ہو جائے گی اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ مقابلہ مکہ کے قریب اور مدینہ سے دور ہوگا اس لئے
کوئی مسلمان بچ کر واپس نہیں آسکے گا.بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اوپر چودہ سو صحابیوں کی
جمعیت کے ساتھ ذ وقعد ہ ۶ ہجری کے شروع میں پیر کے دن بوقت صبح مدینہ سے روانہ ہوئے.اس سفر
میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ آپ کے ہم رکاب تھیں اور مدینہ کا امیر نمیلہ بن عبداللہ کو اور
امام الصلوۃ عبد اللہ بن ام مکتوم کو جو آنکھوں سے معذور تھے مقرر کیا گیا تھا.جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے جو دینہ سے قریباً چھ میل کے فاصلہ پر مکہ کے رستہ پر واقع ہے.تو آپ
نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد قربانی کے اونٹوں کو جو تعداد میں ستر تھے نشان لگائے
جانے کا ارشاد فرمایا اور صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ حاجیوں کا مخصوص لباس جو اصطلاحاً احرام کہلاتا ہے
پہن لیں اور آپ نے خود بھی احرام باندھ لیا ہے اور پھر قریش کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لئے کہ آیا
وہ کسی شرارت کا ارادہ تو نہیں رکھتے ، ایک خبر رساں بُسر بن سفیان نامی کو جو قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتا تھا جو
مکہ کے قرب میں آباد تھے آگے بھجوا کر آہستہ آہستہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے.اور مزید احتیاط کے طور پر
مسلمانوں کی بڑی جمعیت کے آگے آگے رہنے کے لئے عباد بن بشر کی کمان میں میں سواروں کا ایک دستہ
بھی متعین فرمایا ہے جب آپ چند روز کے سفر کے بعد عسفان کے قریب پہنچے جو مکہ سے قریباً دو منزل کے
رستہ پر واقع ہے تو آپ کے خبر رساں نے واپس آکر آپ کی خدمت میں اطلاع دی کہ قریش مکہ بہت
جوش میں ہیں اور آپ کو روکنے کا پختہ عزم کئے ہوئے ہیں ہے حتی کہ ان میں سے بعض نے اپنے جوش
اور وحشت کے اظہار کے لئے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور جنگ کا پختہ عزم کر کے بہر صورت
مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں.یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند جانباز سواروں کا ایک
دستہ خالد بن ولید کی کمان میں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بھجوا دیا ہے اور یہ کہ یہ دستہ
ل : سورة الفتح : ۱۳،۱۲ و تفسیر ابن کثیر متعلق آیات مذکورہ وابن ہشام سے : ابن سعد وابن ہشام وطبری وزرقانی
ے: زرقانی
ابن سعد ه: ابن ہشام
ابن سعد و نمیس
ے بخاری کتاب المغازی باب غزوة الحديبيه عن مسور ومروان
Page 859
۸۴۴
اس وقت مسلمانوں کے قریب پہنچا ہوا ہے اور اس دستہ میں عکرمہ بن ابو جہل بھی شامل ہے وغیرہ وغیرہ.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو تصادم سے بچنے کی غرض سے صحابہ کو حکم دیا کہ مکہ کے معروف
رستہ کو چھوڑ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھیں.چنانچہ مسلمان ایک دشوار گزار اور کٹھن رستہ پر
پڑ کر سمندر کی جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے لے
جب آپ اس نئے رستہ پر چلتے ہوئے حدیبیہ کے قریب پہنچے جو مکہ سے ایک منزل یعنی صرف
نومیل کے فاصلہ پر ہے.اور حدیبیہ کی گھاٹیوں پر سے مکہ کی وادی کا آغاز ہو جاتا ہے تو آپ کی اونٹنی جو
القصوا کے نام سے مشہور تھی اور بہت سے غزوات میں آپ کے استعمال میں رہ چکی تھی یکانت پاؤں پھیلا کر
زمین پر بیٹھ گئی اور با وجود اٹھانے کے اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی.صحابہ نے عرض کیا کہ شاید یہ تھک گئی ہے مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”نہیں نہیں یہ تھکی نہیں اور نہ ہی اس طرح تھک کر بیٹھ جانا اس کی
عادت میں داخل ہے بلکہ حق یہ ہے کہ جس بالا ہستی نے اس سے پہلے اصحاب فیل کے ہاتھی کو مکہ کی طرف
بڑھنے سے روکا تھا اُسی نے اب اس اونٹنی کو بھی روکا ہے.پس خدا کی قسم مکہ کے قریش جو مطالبہ بھی حرم کی
عزت کے لئے مجھ سے کریں گے میں اسے قبول کروں گا.اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹنی کو پھر اٹھنے کی
آواز دی اور خدا کی قدرت کہ اس دفعہ وہ جھٹ اٹھ کر چلنے کو تیار ہوگئی.اس پر آپ اسے وادی حدیبیہ
کے پر لے کنارے کی طرف لے گئے اور وہاں ایک چشمہ کے پاس ٹھہر کر اونٹنی سے نیچے اتر آئے اور
اسی جگہ آپ کے فرمانے پر صحابہ نے ڈیرے ڈال دئے.مسلمانوں کو پانی کی تکلیف اور تکثیر الماء کا معجزہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ صحابہ کی
ایک پارٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی
اور عرض کیا کہ چشمہ کا پانی ختم ہو کر خشک ہو گیا ہے اور اب انسان اور جانور سخت تکلیف میں ہیں.اس
کے لئے کیا کیا جائے؟ آپ نے ایک تیر لیا اور حکم دیا کہ اس تیر کو خشک شدہ چشمہ کی تہ میں نصب کر
ل : ابن ہشام وطبری حالات صلح حدیبیہ
بخاری کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد
ابن سعد
اس سے پہلے دوران سفر میں بھی ایک دفعہ پانی کی تکلیف ہو چکی تھی جب کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سوائے اس
لوٹے کے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال تھا ہر برتن سے پانی خالی ہو گیا تھا.اس موقع پر آپ نے صحابہ کی
طرف سے پانی کی شکایت ہونے پر اپنے لوٹے کے منہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور لوٹے کے منہ کو جھکاتے ہوئے صحابہ
Page 860
۸۴۵
دیا جائے یا اور آپ خود چشمہ کے کنارے پر تشریف لا کر وہاں بیٹھ گئے اور تھوڑ اسا پانی لے کر اسے اپنے
منہ میں ڈالا اور پھر خدا سے دعا کرتے ہوئے یہ پانی اپنے منہ سے چشمہ کے اندر انڈیل دیا اور صحابہ سے
فرمایا کہ اب تھوڑی دیر انتظار کرو.چنانچہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ چشمہ کے اندر اتنا پانی بھر آیا کہ
سب نے اپنی اپنی ضرورت کے لئے استعمال کیا اور پانی کی تکلیف جاتی رہی.اس پر اللہ تعالیٰ نے مزید فضل یہ فرمایا کہ اسی رات یا اس کے قریب بارش بھی ہوگئی.چنانچہ جب صبح
کی نماز کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میدان پانی سے تر بتر تھا.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے صحابہ سے مسکراتے ہوئے فرمایا ” کیا تم جانتے ہو کہ اس بارش کے موقع پر تمہارے خدا نے کیا
ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ نے حسب عادت عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں.آپ نے
فرمایا ” خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے تو یہ صبح حقیقی ایمان کی حالت میں کی ہے
مگر بعض کفر کی حالت میں پڑ کر ڈگمگا گئے.کیونکہ جس بندے نے تو یہ کہا کہ ہم پر خدا کے فضل ورحم
سے بارش ہوئی ہے وہ تو ایمان کی حقیقت پر قائم رہا مگر جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے
کے اثر کے ماتحت ہوئی ہے تو وہ بیشک چاند سورج کا تو مومن ہو گیا لیکن خدا کا اس نے کفر کیا.اس
ارشاد سے جوتو حید کی دولت سے معمور ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سبق دیا کہ بے شک
سلسلہ اسباب و علل کے ماتحت خدا نے اس کا رخانہ عالم کو چلانے کے لئے مختلف قسم کے اسباب مقررفرما
رکھے ہیں اور بارشوں وغیرہ کے معاملہ میں اجرام سماوی کے اثر سے انکار نہیں مگر حقیقی توحید یہ ہے کہ باوجود
درمیانی اسباب کے انسان کی نظر اس وراء الوراء ہستی کی طرف سے غافل نہ ہو جو ان سب اسباب کی
پیدا کرنے والی اور اس کارخانہ عالم کی علت العلل ہے اور جس کے بغیر یہ ظاہری اسباب ایک مردہ کیڑے
سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے.بقیہ حاشیہ سے فرمایا کہ اب اپنے اپنے برتن لاؤ اور بھر لو.راوی بیان کرتا ہے کہ اس وقت آپ کی انگلیوں کے اندر سے
پانی اس طرح پھوٹ پھوٹ کر بہ رہا تھا کہ گویا ایک چشمہ جاری ہے.حتی کہ سب نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے
لیا اور مسلمانوں کی تکلیف جاتی رہی.بخاری کتاب المغازی روایت جابر بن عبد الله وسيرة حلبیہ حالات صلح حدیبیہ.بخاری کتاب الشروط
سے بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الحدیبیہ عن براء بن عازب
بخاری کتاب المغازی حالات صلح حدیبیہ وا ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۷۰
Page 861
۸۴۶
معجزات کے متعلق ایک مختصر اصولی نوٹ یہ سوال کہ اس موقع پر عام قانون قدرت کے
خلاف چشمہ کا پانی کس طرح زیادہ ہو گیا ؟ معجزات
حصہ
کی بحث سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق ہم اس کتاب میں دوسری جگہ ایک اصولی نوٹ درج کر چکے ہیں
اور اس جگہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں.دراصل معجزات کی بحث دو اصولی حصوں میں منقسم ہے.ایک
عقلی دلائل سے تعلق رکھتا ہے جن سے معجزات کا امکان اور ان کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اور دوسرا
حصہ مشاہدہ سے تعلق رکھتا ہے جس سے معجزات کا عملاً وقوع میں آنا ثابت ہوتا ہے.عقلی دلائل کا نتیجہ صرف
اس حد تک ہے کہ معجزہ وقوع میں آسکتا ہے اور یہ کہ انسان کی روحانیت کی تکمیل کے لئے اسے وقوع میں آنا
چاہئے مگر اس سے آگے اس بات کے ثبوت کے لئے کہ معجزہ واقعی ہوتا بھی ہے مشاہدہ کی ضرورت پیش
آتی ہے اور خوش قسمتی سے اس قسم کے مشاہدہ کا وجود ہر نبی کے زمانہ میں اور ہر قوم کی تاریخ میں ملتا ہے مگر
افسوس ہے کہ موجودہ زمانہ کی عالمگیر مادیت نے انسان کے روحانی کمالات اور روحانی حواس کو اس حد تک
خاک میں ملا رکھا ہے کہ مادہ پرستی کے خیالات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا اور انسانیت کے اعلی کمالات زمین
دوز دفینوں کی طرح نظروں سے دور اور آنکھوں سے مستور ہو چکے ہیں.مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد
رکھنی چاہئے کہ خدا کا قانون دو قسم کا ہے.ایک وہ جو اس کی نہ بدلنے والی سنتوں اور اس کے وعدوں کے
ساتھ تعلق رکھتا ہے مثلاً یہ کہ کوئی مردہ زندہ ہو کر اس دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آسکتا ہے اور دوسرا وہ جوان
دو دائروں کے علاوہ ہے مثلاً نیک اور بد بندوں کے ساتھ خدا کے سلوک کے اظہار کا طریق وغیرہ.پس
جہاں تک اول الذکر قانون کا تعلق ہے قرآن شریف بڑے زور کے ساتھ فرماتا ہے کہ وہ بالکل اٹل ہے.اور نہ صرف دنیا کی تمام علمی و عملی ترقی بلکہ خدا کی شان اور وقار کا اظہار بھی اس کے اہل ہونے کے ساتھ
وابستہ ہے لیکن مؤخر الذکر قانون حالات کے اختلاف کے ساتھ اپنی صورت بدل سکتا ہے اور اس کا بدلنا
خدا کی شان کے خلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق ہے اور اسی تبدیلی کے غیر معمولی ظہور کا نام معجزہ ہے.دراصل اگر اس دنیا کا کوئی خدا ہے جس نے اس دنیا کی چیزوں کو اور ان چیزوں کے خواص کو پیدا کیا ہے اور
یہ خدا اپنے تخت حکومت سے معزول و معطل نہیں ہو گیا اور اپنے قانون کا غلام نہیں بن گیا تو پھر اس خدا
میں یہ قوت تسلیم کرنی پڑے گی کہ اپنی سنت اور وعدہ کی باتوں کو الگ رکھ کر جن میں بہر حال کوئی تبدیلی نہیں
لے: دیکھئے کتاب ہذا حصہ دوم
سورۃ الاحزاب : ۶۳۶۲
: سورۃ المومنون : ۹۶ تا ۱۰۱
Page 862
۸۴۷
ہو سکتی وہ کسی حقیقی ضرورت کے وقت اپنے ایسے قانون کو جو اس کی کسی سنت یا وعدہ کے دائرہ سے تعلق نہیں
رکھتا خاص استثنائی رستہ پر چلا سکتا ہے یا بعض مخفی اسباب کے ذریعہ ایک ایسا ظاہری تغیر پیدا کرسکتا
ہے
جو بظاہراستثنا کا رنگ رکھتا ہو اور اسی استثنایا خاص تقدیر الہی کے غیر معمولی ظہور کا نام معجزہ ہے.اور معجزہ کی ضرورت اس طرح ثابت ہے کہ جیسا کہ ہر سمجھ دار انسان محسوس کرے گا محض عقلی دلیلوں
کا وجود خدا کے متعلق اس حد تک کا ایمان ہرگز پیدا نہیں کر سکتا جو انسان کی روحانی زندگی کے لئے ضروری
ہے کیونکہ عقلی دلیلیں زیادہ سے زیادہ یہ ثابت کر سکتی ہیں کہ اس کارخانہ عالم کا کوئی خالق و مالک ہونا چاہئے
مگر ظاہر ہے کہ یہ ہونا چاہیے والا مقام محض ایک قیاس کا مقام ہے جسے قطعی اور زندہ یقین میں بدلنے
کے لئے جسے ہم ” ہے کے مقام سے تعبیر کر سکتے ہیں الہام الہی اور معجزہ کی ضرورت پیش آتی ہے.اس لئے ہر نبی اور رسول کے ساتھ معجزہ کا وجود لازم و ملزوم کے طور پر رہا ہے اور اسلامی معجزات سے انکار
کرنے والوں کی خود اپنی کتب معجزات کے ذکر سے ( جن میں افسوس ہے کہ اکثر فرضی اور بلاثبوت اور
سنت الہی کے خلاف ہیں ) بھری پڑی ہیں.باقی رہا مشاہدہ کا سوال سوجن ابتدائی لوگوں نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کئے ہیں وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور دن رات
آپ کی صحبت میں رہنے والے تھے انہوں نے اپنا ذاتی مشاہدہ ہی بیان کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر
روایت صحیح ہوا اور راوی سچ بولنے والا اور سمجھ دار ہو تو یہ مشاہدہ اسی طرح قابل قبول ہے جس طرح کہ
دنیا کے دوسرے پختہ مشاہدات قابل قبول ہوتے ہیں اور گوموجودہ مادی زمانہ میں روحانی اہل کمال کا
وجود عنقا کا رنگ رکھتا ہے مگر اس زمانہ میں بھی مقدس بانی سلسلہ احمدیہ نے معجزات کے متعلق معترضین کو
جواب دیتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ :
کرامت گرچہ بے نام و نشان است بیا بنگر ز غلمان
یعنی گو اس زمانہ میں معجزات کا وجود بے نام ونشان ہو چکا ہے مگر اے منکر اسلام ! آ
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ پر معجزات کا مشاہدہ کر لے.“
ایک اور اصولی بات جو معجزات کے متعلق یاد رکھنی ضروری ہے اور جسے نظر انداز کرنے سے اکثر
مذاہب میں بعد میں آنے والوں کی دست برد سے جھوٹے اور فرضی معجزات کا وجود پیدا ہو گیا ہے یہ ہے کہ
معجزات کی غرض و غایت چونکه ایمان پیدا کرنا یا پیدا شده ایمان کو مضبوط کرنا ہوتی ہے اور ایمان کے لئے
اس کے ابتدائی مراحل میں کسی قدر اخفاء کا پردہ ضروری ہے اور اسی لئے قرآن شریف نے اپنی ابتدا میں ہی
Page 863
۸۴۸
ایمان بالغیب کے اصول کو پیش کیا ہے.کیونکہ کامل مشاہدہ کے بعد ایمان کسی انعام یا تعریف کا حق دار
نہیں رہتا اس لئے سنت اللہ اس طرح پر واقع ہوئی ہے کہ بچے معجزات
کبھی بھی ایسی صورت میں ظاہر نہیں
ہوتے کہ گویا بالکل شہود کا رنگ پیدا ہو جائے بلکہ کسی نہ کسی جہت سے کچھ نہ کچھ اخفاء کا پردہ باقی رکھا جاتا
ہے.اسی لئے اہل اللہ نے معجزات کی مثال دن کی تیز روشنی سے نہیں دی بلکہ ایک ایسی چاندنی رات کی
روشنی سے دی ہے جس میں کسی قدر بادل بھی ہوں.ایسی صورت میں جہاں ایک طرف توجہ اور غور سے
دیکھنے والوں کو رستہ نظر آ جاتا ہے وہاں دوسری طرف ضدی اور کجر ولوگوں کے لئے شک کی گنجائش بھی باقی
رہتی ہے.البتہ بعض اوقات ایسے معجزات میں جو صرف ان مومنوں کو دکھائے جاتے ہیں جو ایمان کے
ابتدائی مراحل سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں کسی قدر شہود کا رنگ پیدا کر دیا جاتا ہے مگر یہ ایک لمبا اور
بار یک سوال ہے جو تفصیلی بحث چاہتا ہے اور اس مختصر اور ضمنی نوٹ میں تفصیل کی گنجائش نہیں.خلاصہ کلام یہ کہ معجزات اور آیات کا وجود برحق ہے اور اسلام اسے تسلیم کرتا اور ہر نبی اور رسول کے
زمانہ میں اس کے ظہور کا دعویٰ فرماتا ہے مگر اول تو کوئی معجزہ خدا کی کسی نہ بدلنے والی سنت یا اس کے
کسی وعدہ کے خلاف نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر ایسا ہو تو دنیا میں اندھیر پڑ جائے اور قرآن شریف نے صراحت
کے ساتھ ایسے معجزات کے وجود سے انکار کیا ہے." اور دوم کسی معجزہ میں جو منکرین کو دکھانا مقصود ہو
نصف النہار والی روشنی پیدا نہیں ہو سکتی.کیونکہ یہ ایمان بالغیب کے اصول کے خلاف ہے جسے
قرآن شریف نے اپنی ابتدا میں ہی بڑے زور کے ساتھ پیش کیا ہے.مگر ان دونوں حدود کے اندراندر
معجزہ ہو سکتا ہے اور ہر نبی کے زمانہ میں ہوتا رہا ہے اور حق یہ ہے کہ اگر ایسے معجزات کا دروازہ بند ہو جائے
تو دنیار وحانی طور پر زندہ ہی نہیں رہ سکتی.قریش کے ساتھ صلح کی گفتگو کا آغاز معجزات کے متعلق یہ مختصر اور اصولی نوٹ دینے کے بعد ہم
پھر اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں.ہم بتا چکے ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی وادی میں پہنچ کر اس وادی کے چشمہ کے پاس قیام کیا.جب
صحابہ اس جگہ ڈیرے ڈال چکے تو قبیلہ خزاعہ کا ایک نامور رئیس بدیل بن ورقا نامی جو قریب ہی کے علاقہ
میں آباد تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے آیا اور اس نے آپ
: سورة البقرة : ۴ دیکھو براہین احمدیہ حصہ پنجم مصنفہ مقدس بانی سلسلہ احمدیہ صفحه ۳۳
: سورۃ الاحزاب : ۶۳ وسورة آل عمران : ۱۰
: سورة البقرة : ۴
Page 864
۸۴۹
سے عرض کیا کہ ملکہ کے رؤساء جنگ کے لئے تیار کھڑے ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے
دیں گے.آپ نے فرمایا ”ہم تو جنگ کی غرض سے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں
اور افسوس ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش مکہ کو جنگ کی آگ نے جلا جلا کر خاک کر رکھا ہے مگر پھر بھی یہ
لوگ باز نہیں آتے اور میں تو ان لوگوں کے ساتھ اس سمجھوتہ کے لئے بھی تیار ہوں کہ وہ میرے خلاف
جنگ بند کر کے مجھے دوسرے لوگوں کے لئے آزاد چھوڑ دیں.لیکن اگر انہوں نے میری اس تجویز کو بھی رد
کر دیا اور بہر صورت جنگ کی آگ کو بھڑکائے رکھا تو مجھے بھی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے کہ پھر میں بھی اس مقابلہ سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ یا تو میری جان اس رستہ میں
قربان ہو جائے اور یا خدا مجھے فتح عطا کرے.اگر میں ان کے مقابلہ میں آکر مٹ گیا تو قصہ ختم ہوا لیکن
اگر خدا نے مجھے فتح عطا کی اور میرے لائے ہوئے دین کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر مکہ والوں کو بھی ایمان لے
آنے میں کوئی تامل نہیں ہونا چاہئے ، بدیل بن ورقا پر آپ کی اس مخلصانہ اور دردمندانہ تقریر کا بہت اثر
ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ مہلت دیں کہ میں مکہ جا کر آپ کا پیغام پہنچاؤں اور
مصالحت کی کوشش کروں.آپ نے اجازت دی اور بریل اپنے قبیلہ کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر
مکہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے
جب بدیل بن ورقا مکہ میں پہنچا تو اس نے قریش کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں اس شخص (یعنی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) [ عرب کا دستور تھا کہ ایسے موقعوں پر جب ایک معروف شخص کے متعلق
گفتگو کرنی ہو تو نام لینے کی بجائے یہ شخص یا اس شخص “ وغیرہ کے لفظ استعمال کرتے تھے] کے پاس
سے آ رہا ہوں اور میرے سامنے اس نے ایک تجویز پیش کی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ذکر
کروں.اس پر قریش کے جو شیلے اور غیر ذمہ دار لوگ کہنے لگے.ہم اس شخص کی کوئی بات سننے کے لئے
تیار نہیں مگر اہل الرائے اور ثقہ لوگوں نے کہا ہاں ہاں جو تجویز بھی ہے وہ ہمیں بتاؤ.چنانچہ بدیل نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تجویز کا اعادہ کیا.اس پر ایک شخص عروہ بن مسعود نامی جو قبیلہ
ثقیف کا ایک بہت با اثر رئیس تھا اور اس وقت مکہ میں موجود تھا کھڑا ہو گیا اور قدیم عربی انداز میں قریش
سے کہنے لگا "اے لوگو! کیا میں تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہوں؟“ انہوں نے کہا ”ہاں“.پھر اس نے
کہا ” کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں ؟ انہوں نے کہا ”ہاں“.پھر عروہ نے کہا ” کیا
ل : بخاری کتاب الشروط
Page 865
۸۵۰
تمہیں مجھ پر کسی قسم کی بے اعتمادی ہے؟ قریش نے کہا ہرگز نہیں “.اس نے کہا تو پھر میری یہ رائے
ہے کہ اس شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے آپ کے سامنے ایک عمدہ بات پیش کی ہے.آپ کو چاہیے کہ
اس تجویز کو قبول کر لیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر
ید گفتگو کروں.قریش نے کہا ”بے شک آپ جائیں اور گفتگو کریں.مزید
66
عروہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک روح پرور نظارہ کی خدمت میں آیا اور آپ
کے ساتھ گفتگو شروع کی.آپ نے اس کے سامنے اپنی وہی تقریر دوہرائی جو اس سے قبل آپ بدیل بن
ورقا کے سامنے فرما چکے تھے.عروہ اصولاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ متفق تھا مگر قریش کی
سفارت کا حق ادا کرنے اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ شرائط محفوظ کرانے کی غرض سے کہنے
لگا.اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اگر آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کو ملیا میٹ کر دیا تو کیا آپ نے
عربوں میں کسی ایسے آدمی کا نام سنا ہے جس نے آپ سے پہلے ایسا ظلم ڈھایا ہو.لیکن اگر بات دگر گوں
ہوئی یعنی قریش کو غلبہ ہو گیا تو خدا کی قسم مجھے آپ کے ارد گرد ایسے منہ نظر آرہے ہیں کہ انہیں بھاگتے ہوئے
دیر نہیں لگے گی اور یہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے.حضرت ابوبکر جو اس وقت آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے عروہ کے یہ الفاظ سن کر غصہ سے بھر گئے اور فرمانے لگے ” جاؤ جاؤ اور لات کی
شرمگاہ کو چومتے پھرو.کیا ہم خدا کے رسول کو چھوڑ جائیں گے ؟ ۲۰ عروہ نے طیش میں آکر پوچھا یہ کون
شخص ہے جو اس طرح میری بات کا تھا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابوبکر ہیں.ابوبکر کا نام سن کر عروہ کی
آنکھیں شرم سے نیچی ہو گئیں.کہنے لگا اے ابوبکر! اگر میرے سر پر تمہارا ایک بھاری احسان نہ ہوتا کے تو
خدا کی قسم میں تمہیں اس وقت بتاتا کہ ایسی بات کا جو تم نے کہی ہے کس طرح جواب دیتے ہیں.یہ کہہ کر
ل بخاری کتاب الشروط
لات قبیلہ بنو ثقیف کا ایک مشہور بت تھا اور حضرت ابوبکر کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ بت پرست ہوا اور ہم لوگ
خدا پرست ہیں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ تم تو بتوں کی خاطر صبر و ثبات دکھاؤ اور ہم خدا پر ایمان لاتے ہوئے رسول خدا کو
چھوڑ کر بھاگ جائیں؟
ے عروہ ایک دفعہ بھاری قرضہ کے نیچے دب گیا تھا اور حضرت ابو بکڑ نے اپنے پاس سے اس کا قرض ادا کر کے اس
کی جان چھڑا ئی تھی.
Page 866
۸۵۱
66
عروہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا اور اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنے نقطہ نظر کی طرف کھینچ لانے کی تدبیر کرتا رہا اور گاہے گاہے عرب کے دستور کے مطابق آپ کی
ریش مبارک کو بھی ہاتھ لگا دیتا تھا.مگر جب کبھی بھی وہ ایسا کرتا ایک مخلص صحابی جن کا نام مغیرہ بن شعبہ تھا
اور جو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے (اور رشتہ میں عروہ کے بھتیجے تھے ) اپنی
تلوار کے نیام سے عروہ کا ہاتھ جھٹک کر پرے کر دیتے اور کہتے اپنا نا پاک ہاتھ رسول مقبول کے مبارک
چہرہ سے دور رکھو.چونکہ اس وقت مغیرہ کا چہرہ ایک خود کے اندر ڈھکا ہوا تھا عروہ نے انہیں نہ پہچانتے
ہوئے پوچھا.یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے.‘“ عروہ نے حقارت اور غصہ سے کہا
”اے بے وفا ! کیا تجھے میرا احسان بھول گیا ہے؟ اس پر مغیرہ شرم سے جھینپ گئے.اس وقت عروہ نے
اپنے اردگرد فخر کی نگاہ ڈالی مگر یہی نگاہ اسے گھائل کر گئی.کیونکہ عروہ نے اس وقت صحابہ کی جماعت کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس طرح جمع پایا جس طرح شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں
اور خود عروہ کا اپنا بیان ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے جوش محبت واخلاص کا یہ عالم تھا کہ اگر پانی پیتے
ہوئے آپ کے منہ سے کوئی قطرہ گرتا تو صحابہ اسے شوق سے اپنے ہاتھوں پر لیتے اور برکت کے خیال سے
اسے اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیتے اور جب آپ کسی چیز کا ارشاد فرماتے تو لوگ آپ کی آواز پر
اس طرح لپکتے کہ گویا ایک مقابلہ ہو جاتا تھا.اور جب آپ وضو کرتے تو صحابہ اس شوق سے آپ کو
وضو کر وانے کے لئے آگے بڑھتے کہ گویا اس خدمت کے حصول کے لئے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے
اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ خاموش ہو کر ہمہ تن گوش ہو جاتے اور محبت اور رعب کی وجہ سے ان
کی نظر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ نہیں سکتی تھیں.عروہ ان روح پرور نظاروں کو دیکھ کر اور آپ کے ساتھ گفتگو ختم کر کے قریش کی طرف لوٹا اور جاتے
ہی قریش سے کہنے لگا "اے لوگو! میں نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے.بادشاہوں کے دربار میں شامل ہوا
ہوں اور قیصر و کسری اور نجاشی کے سامنے بطور وفد کے پیش ہو چکا ہوں مگر خدا کی قسم جس طرح میں نے
محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) کے صحابیوں
کومحمد کی عزت کرتے دیکھا ہے ایسا میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا.“
ل : عروہ نے مغیرہ کے اسلام لانے سے پہلے ان پر یہ احسان کیا تھا کہ ان کی طرف سے بعض قتلوں کا خون بہا ادا کیا تھا
اور عربوں میں احسان کی بڑی قدرو قیمت تھی جسے اسلام نے اور بھی بڑھا دیا تھا.: بخاری کتاب الشروط
Page 867
۸۵۲
پھر اس نے اپنا وہ سارا مشاہدہ بیان کیا جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا تھا اور
آخر میں کہنے لگا میں پھر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی تجویز ایک منصفانہ تجویز ہے
166
اسے قبول کر لینا چاہئے.عروہ کی یہ گفتگوسن کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک رئیس نے جس کا نام حلیس بن علقمہ تھا.قریش سے کہا
اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جاتا ہوں.‘انہوں نے کہا ”ہاں بے
شک جاؤ.چنانچہ یہ شخص حدیبیہ میں آیا اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے دیکھا
تو صحابہ سے
فرمایا یہ شخص جو ہماری طرف آرہا ہے ایسے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے مناظر کو پسند
کرتے ہیں.پس فوراً اپنے قربانی کے جانوروں کو اکٹھا کر کے اس کے سامنے لاؤ تا کہ اسے پتہ لگے اور
احساس پیدا ہو کہ ہم کسی غرض سے آئے ہیں.چنانچہ صحابہ اپنے قربانی کے جانوروں کو ہنکاتے ہوئے اور
تکبیروں کی آواز بلند کرتے ہوئے اس کے سامنے جمع ہو گئے.جب اس نے یہ نظارہ دیکھا تو کہنے لگا.سبحان
اللہ سبحان اللہ یہ تو حاجی لوگ ہیں.انہیں بیت اللہ کے طواف سے کسی طرح روکا نہیں جاسکتا.“
چنانچہ وہ جلدی ہی قریش کی طرف واپس لوٹ گیا اور قریش سے کہنے لگا ” میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں
نے اپنے جانوروں کے گلے میں قربانی کے بار باندھ رکھے ہیں اور ان پر قربانی کے نشان لگائے ہوئے ہیں.پس یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ انہیں طواف کعبہ سے روکا جائے.قریش میں اس وقت ایک سخت انتشار کی کیفیت پیدا ہورہی تھی اور لوگوں کی دو پارٹیاں بن گئی
تھیں.ایک پارٹی بہر صورت مسلمانوں کو واپس لوٹانے پر مصر تھی اور مقابلہ کے خیالات پر سختی سے قائم
تھی.مگر دوسری پارٹی اسے اپنی قدیم مذہبی روایات کے خلاف پا کر خوف زدہ ہو رہی تھی اور کسی باعزت
سمجھوتہ کی متمنی تھی اس لئے فیصلہ معلّق چلا جار ہا تھا.اس موقع پر ایک اور عربی رئیس مکر ز بن حفص نامی نے
قریش سے کہا ” مجھے جانے دو میں کوئی فیصلہ کی راہ نکالوں گا.قریش نے کہا اچھا تم بھی کوشش کر کے
دیکھ لو.چنانچہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے
آتے دیکھا تو فرمایا خدا خیر کرے یہ آدمی تو اچھا نہیں.بہر حال مکرز آپ کے پاس آیا اور گفتگو کرنے
لگا.مگر ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ مکہ کا ایک نامور رئیس سہیل بن عمر و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
بخاری کتاب الشروط
: بخاری کتاب الشروط
: ابن ہشام وابن سعد
Page 868
۸۵۳
میں حاضر ہوا جسے غالبا قریش نے اپنی گھبراہٹ میں مکرز کی واپسی کا انتظار کرنے کے بغیر بھجوادیا
تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے دیکھا تو فرمایا یہ سہیل آتا ہے.اب خدا نے چاہا تو معاملہ
آسان ہو جائے گا.کفار مکہ کی فتنہ انگیزی اس موقع پر ایک ضمنی مگر ہم واقعہ کا ذکر ضروری ہے.وہ یہ کہ جب قریش کی
طرف سے پے در پے سفیر آنے شروع ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ محسوس کر کے آپ کی طرف سے بھی کوئی فہمیدہ شخص قریش کی طرف جانا چاہئے جو انہیں ہمدردی
اور دانائی کے ساتھ مسلمانوں کا زاویہ نظر سمجھا سکے ایک شخص خراش بن امیہ کو اس کام کے لئے چنا جو
قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتا تھا.یعنی وہی قبیلہ جس سے قریش کے سب سے پہلے سفیر بدیل بن ورقا کا تعلق تھا
اور اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش کو سواری کے لئے خود اپنا ایک اونٹ عطا فرمایا.خراش
قریش کے پاس گیا مگر چونکہ ابھی یہ گفتگو کا ابتدائی مرحلہ تھا اور نو جوانان قریش بہت جوش میں تھے ایک
جو شیلے نو جوان عکرمہ بن ابو جہل نے خراش کے اونٹ پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا جس کے عربی دستور کے
مطابق یہ معنی تھے کہ ہم تمہاری نقل و حرکت کو جبر اردو کہتے ہیں.علاوہ ازیں قریش کی یہ جوشیلی پارٹی خود
خراش پر بھی حملہ کرنا چاہتی تھی مگر بڑے بوڑھوں نے بیچ بچاؤ کر کے اس کی جان بچائی اور وہ اسلامی کیمپ
میں واپس آگیا.قریش مکہ نے اسی پر اکتفانہیں کی بلکہ اپنے جوش میں اندھے ہو کر اس بات کا بھی ارادہ کیا کہ اب
جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ملکہ سے اس قدر قریب اور مدینہ سے اتنی دور آئے ہوئے
ہیں تو ان پر حملہ کر کے جہاں تک ممکن ہو نقصان پہنچایا جائے.چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے چالیس
پچاس آدمیوں کی ایک پارٹی حدیبیہ کی طرف روانہ کی اور اس گفت وشنید کے پردے میں جو اس وقت
فریقین میں جاری تھی ان لوگوں کو ہدایت دی کہ اسلامی کیمپ کے اردگر دگھومتے ہوئے تاک میں رہیں
اور موقع پا کر مسلمانوں کا نقصان کرتے رہیں ہے بلکہ بعض روایتوں سے یہاں تک پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ
تعداد میں اتنی تھے اور اس موقع پر قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کی تھی.هے
ل سہیل کا لفظ سہل سے نکلا ہے جس کے معنی آسانی کے ہیں
ے : ابن ہشام وزرقانی
ه مسند احمد ومسلم وابوداؤد بحوالہ ابن کثیر جلد ۴ صفه ۱۹۲
بخاری کتاب الشروط وزرقانی
طبری و ابن ہشام حالات حدیبیہ
Page 869
۸۵۴
مگر بہر حال خدا کے فضل سے مسلمان اپنی جگہ ہوشیار تھے.چنانچہ قریش کی اس سازش کا راز کھل گیا اور
یہ لوگ سب کے سب گرفتار کر لئے گئے یا مسلمانوں کو اہل مکہ کی اس حرکت پر جو اشہرحرم میں اور پھر
گویا حرم کے علاقہ میں کی گئی سخت طیش تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا اور
مصالحت کی گفتگو میں روک نہ پیدا ہونے دی.یہ اہل مکہ کی اس حرکت کا قرآن شریف نے بھی ذکر کیا ہے
چنانچہ فرماتا ہے:
هُوَ الَّذِي كَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ
أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ
یعنی ”خدا نے اپنے فضل سے کفار کے ہاتھوں کو مکہ کی وادی میں تم سے روک کر رکھا اور
تمہاری حفاظت کی اور پھر جب تم نے ان لوگوں پر غلبہ پالیا اور انہیں اپنے قابو میں کر لیا تو خدا
نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک کر رکھا.“
مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمان کی سفارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش
کی اس شرارت کو دیکھا اور ساتھ ہی
خراش بن امیہ سے اہل مکہ کے جوش وخروش کا حال سنا تو قریش کو ٹھنڈا کرنے اور راہ راست پر لانے کی
غرض سے ارادہ فرمایا کہ کسی ایسے بااثر شخص کو مکہ میں بھجوائیں جو مکہ ہی کا رہنے والا ہو اور قریش کے کسی
معزز قبیلہ سے تعلق رکھتا ہو.چنانچہ آپ نے حضرت عمر بن الخطاب سے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ آپ مکہ میں
جائیں اور مسلمانوں کی طرف سے سفارت کا فرض سرانجام دیں.حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ
جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگ میرے سخت دشمن ہورہے ہیں اور اس وقت مکہ میں میرے قبیلہ کا کوئی با اثر آدمی
موجود نہیں جس کا اہل مکہ پر دباؤ ہو.اس لئے میرا یہ مشورہ ہے کہ کامیابی کا رستہ آسان کرنے کے لئے اس
خدمت کے لئے عثمان بن عفان کو چنا جائے جن کا قبیلہ بنو امیہ ) اس وقت بہت بااثر ہے اور مکہ والے
عثمان کے خلاف شرارت کی جرات نہیں کر سکتے اور کامیابی کی زیادہ امید ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس مشورہ کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان سے ارشاد فرمایا کہ وہ مکہ جائیں اور قریش کو مسلمانوں کے
لے : اس واقعہ کے بارے میں روایات کسی قدر مختلف ہیں.ہم نے اس جگہ بغیر خاص تحقیق کے معروف روایات کو لے لیا ہے.: ابن ہشام و طبری و زرقانی
: سورة الفتح : ۲۵
Page 870
۸۵۵
پُر امن ارادوں اور عمرہ کی نیت سے آگاہ کریں.اور آپ نے حضرت عثمان کو اپنی طرف سے ایک تحریر
بھی لکھ کر دی جور و ساء قریش کے نام تھی.اس تحریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی
غرض بیان کی اور قریش کو یقین دلایا کہ ہماری نیت صرف ایک عبادت کا بجالانا ہے اور ہم پر امن صورت
میں عمرہ بجالا کر واپس چلے جائیں گے.آپ نے حضرت عثمان سے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں جو کمزور مسلمان
ہیں انہیں بھی ملنے کی کوشش کرنا اور ان کی ہمت بڑھانا اور کہنا کہ ذرا ورصبر سے کام لیں خدا عنقریب
کامیابی کا دروازہ کھولنے والا ہے.یہ پیغام لے کر حضرت عثمان مکہ میں گئے اور ابوسفیان سے مل کر جو اس زمانہ میں مکہ کا رئیس اعظم تھا اور
حضرت عثمان کا قریبی عزیز بھی تھا اہل مکہ کے ایک عام مجمع میں پیش ہوئے.اس مجمع میں حضرت عثمان
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پیش کی جو مختلف رؤساء قریش نے فرداً فرداً بھی ملاحظہ کی مگر با وجود
اس کے سب لوگ اپنی اس ضد پر قائم رہے کہ بہر حال مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے کے
حضرت عثمان کے زور دینے پر قریش نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو ہم تم کو ذاتی طور پر طواف
بیت اللہ کا موقع دے دیتے ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں.حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول
اللہ
تو مکہ سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں؟ مگر قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثمان
مایوس ہو کر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے.اس موقع پر مکہ کے شریر لوگوں کو یہ شرارت سوجھی کہ انہوں
نے غالبا اس خیال سے کہ اس طرح ہمیں مصالحت میں زیادہ مفید شرائط حاصل ہوسکیں گی حضرت
عثمان اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں روک لیا.اس پر مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور ہوئی کہ اہل مکہ نے
حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے.بیعت رضوان یہ خبر حدیبیہ میں پہنچی تو مسلمانوں میں سخت جوش پیدا ہوا کیونکہ عثمان آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور معزز ترین صحابہ میں سے تھے اور مکہ میں بطور اسلامی سفیر
کے گئے تھے اور یہ دن بھی اشہر حرم کے تھے اور پھر مکہ خود حرم کا علاقہ تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فوراً تمام مسلمانوں میں اعلان کر کے انہیں ایک بول ( کیکر) کے درخت کے نیچے جمع کیا اور جب صحابہ جمع
ہو گئے تو آپ نے اس خبر کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ اطلاع درست ہے تو خدا کی قسم ہم اس جگہ سے اس
ابن ہشام
زرقانی
: زرقانی جلد ۲ صفحه ۲۰۶
: ابن ہشام وابن سعد
Page 871
۸۵۶
وقت تک نہیں ملیں گے کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں.پھر آپ نے صحابہ سے
فرمایا ” آؤ اور میرے ہاتھ پر
ہاتھ رکھ کر ( جو اسلام میں بیعت کا طریق ہے) یہ عہد کرو کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹھ نہیں دکھائے گا اور اپنی
جان پر کھیل جائے گا مگر کسی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا.اس اعلان پر صحابہ بیعت کے لئے اس طرح
لیکے کہ ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے.اور ان چودہ پندرہ سو مسلمانوں کا ( کہ یہی اس وقت اسلام
کی ساری پونجی تھی ) ایک ایک فرد اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری دفعہ بک گیا." جب بیعت
ہو رہی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا " یہ عثمان کا ہاتھ
ہے کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس مقدس سودے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا لیکن اس وقت وہ خدا اور
اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے.اس طرح یہ بجلی کا سا منظر اپنے اختتام کو پہنچا.اسلامی تاریخ میں یہ بیعت بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے یعنی وہ بیعت جس میں مسلمانوں
نے خدا کی کامل رضا مندی کا انعام حاصل کیا.قرآن شریف نے بھی اس بیعت کا خاص طور پر ذکر فر مایا
ہے.چنانچہ فرماتا ہے.لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا
یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مسلمانوں سے جب کہ اے رسول ! وہ ایک درخت کے نیچے
تیری بیعت کر رہے تھے کیونکہ اس بیعت سے ان کے دلوں
کا مخفی اخلاص خدا کے ظاہری علم میں
آ گیا سوخدا نے بھی ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہیں ایک قریب کی فتح کا انعام عطا کیا.“
صحابہ کرام بھی ہمیشہ اس بیعت کو بڑے فخر اور محبت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر
بعد میں آنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم تو مکہ کی فتح کو فتح شمار کرتے ہومگر ہم بیعت رضوان ہی کو
فتح خیال کرتے تھے.اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ بیعت اپنے کوائف کے ساتھ مل کر ایک نہایت عظیم الشان
ل : یہ بیعت ایک ہی دفعہ اکٹھی نہیں ہوئی بلکہ تین دفعہ باری باری کر کے ٹکڑیوں میں ہوئی تھی.طبری جلد ۲ صفحہ ۱۵۴۴
: سوائے شاید ایک شخص جد بن قیس کے جس کے متعلق ایک روایت آتی ہے کہ وہ منافق تھا اور بیعت کے وقت اپنے
اونٹ کے پیچھے چھپ گیا تھا.(ابن ہشام واسد الغابہ )
: طبری وابن ہشام وابن سعد ۴ : بخاری باب مناقب عثمان
سورة الفتح :
۱۹ :
بخاری کتاب المغازی حالات صلح حد
: ابن سعد
Page 872
۸۵۷
فتح تھی.نہ صرف اس لئے کہ اس نے آئندہ فتوحات کا دروازہ کھول دیا بلکہ اس لئے بھی کہ اس سے اسلام
کی اس جاں فروشانہ روح کا جو دین محمدی کا گویا مرکزی نقطہ ہے ایک نہایت شاندار رنگ میں اظہار ہوا
اور فدائیان اسلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ اپنے رسول اور اس رسول کی لائی ہوئی صداقت کے لئے
ہر میدان میں اور اس میدان کے ہر قدم پر موت وحیات کے سودے کے لئے تیار ہیں.اسی لئے صحابہ
کرام بیعت رضوان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ بیعت موت کے عہد کی بیعت تھی یعنی اس عہد
کی بیعت تھی کہ ہر مسلمان اسلام کی خاطر اور اسلام کی عزت کی خاطر اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر پیچھے
نہیں ہٹے گا.اور اس بیعت کا خاص پہلو یہ تھا کہ یہ عہد و پیمان صرف منہ کا ایک وقتی اقرار نہیں تھا جو
عارضی جوش کی حالت میں کر دیا گیا ہو بلکہ دل کی گہرائیوں کی آواز تھی جس کے پیچھے مسلمانوں کی ساری
طاقت ایک نقطہ واحد پر جمع تھی.جب قریش کو اس بیعت کی اطلاع پہنچی تو وہ خوف زدہ ہو گئے.اور نہ صرف حضرت عثمان اور
ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دیاہے بلکہ اپنے ایلچیوں کو بھی ہدایت دی کہ اب جس طرح بھی ہو مسلمانوں کے
ساتھ معاہدہ کر لیں مگر یہ شرط ضرور رکھی جائے کہ اس سال کی بجائے مسلمان آئندہ سال آکر عمرہ بجالائیں
اور بہر حال اب واپس چلے جائیں.دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے یہ عہد کر چکے
تھے.میں اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو حرم الحرم اور بیت اللہ کے احترام کے خلاف ہو
اور چونکہ آپ کو خدا نے یہ بشارت دے رکھی تھی کہ اس موقع پر قریش کے ساتھ مصالحت آئندہ
کامیابیوں کا پیش خیمہ بننے والی ہے اس لئے گویا فریقین کے لحاظ سے یہ ماحول مصالحت کا ایک
نہایت عمدہ ماحول تھا اور اسی ماحول میں سہیل بن عمر و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ
نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہوتا نظر آتا ہے.یہ بات روایتوں سے واضح نہیں ہوتی کہ
سهیل معین طور پر کس مرحلہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آیا اس کا آنا حضرت
عثمان کے مکہ کی طرف جانے سے پہلے تھا یا کہ بعد.اور اس بارے میں بعض روایات میں کسی قدر
اختلاف و انتشار بھی پایا جاتا ہے مگر بہر حال یہ بات مسلم ہے کہ صلح کی وہ تحریر جس کا ہم اب ذکر کرنے
لگے ہیں وہ سہیل بن عمرو کے ذریعہ ہی تکمیل کو پہنچی اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ قریش کے یہ جملہ سفرا
جو یکے بعد دیگرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ سب کے سب بعد میں اسلام لاکر
بخاری حالات صلح حدیبیہ
زرقانی جلد ۲ صفحه ۲۰۸ ے : ابن ہشام وطبری
Page 873
ΛΩΛ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو گئے یا سوائے مکر ز بن حفص کے جسے دیکھتے ہی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس شخص سے بداخلاقی اور غداری کی بو آتی ہے..صلح کی گفتگو سہیل بن عمرو نے جو گفتگو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی اور جس رنگ میں یہ
اہم تاریخی معاہدہ ضبط تحریر میں آیا وہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دلچسپ ورق ہے
جسے سب محمد ثین اور مؤرخین نے بڑے شوق اور تفصیل کے ساتھ سپرد قلم کیا ہے.ہم اس جگہ صحیح بخاری
کی روایت کے مطابق اس واقعہ کی موٹی موٹی تفاصیل ہدیہ ناظرین کرتے ہیں.امام بخاری جو روایت
کے لحاظ سے جملہ محدثین میں بلند ترین مقام رکھتے ہیں اس دلچسپ واقعہ کو مندرجہ ذیل صورت میں
بیان کرتے ہیں.جب سہیل بن عمر و آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا یہ سہیل
آتا ہے اب خدا نے چاہا تو معاملہ سہل ہو جائے گا.سے بہر حال سہیل آیا اور آتے ہی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہنے لگا.آؤ جی (اب لمبی بحث جانے دو ) ہم معاہدہ کے لئے تیار ہیں.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی تیار ہیں.اور اس ارشاد کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سیکرٹری ( حضرت علی) کو بلوا
لیا (اور چونکہ شرائط پر ایک عمومی بحث پہلے ہو چکی تھی اور تفاصیل نے ساتھ ساتھ طے پانا تھا) اس لئے
کاتب کے آتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل صلح کے لئے تو
تیار تھا مگر قریش کے حقوق کی حفاظت اور اہل مکہ کے اکرام کے لئے بھی بہت چوکس رہنا چاہتا تھا فوراً بولا
یہ رحمن کا لفظ کیسا ہے ہم اسے نہیں جانتے.جس طرح عرب لوگ ہمیشہ سے لکھتے آئے ہیں اس طرح
لکھو یعنی بِاسْمِكَ اللهُمَّ دوسری طرف مسلمانوں کے لئے بھی قومی عزت اور مذہبی غیرت کا سوال تھا
وہ بھی اس تبدیلی پر فوراً چونک پڑے اور کہنے لگے ہم تو ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں گے مگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر مسلمانوں کو خاموش کرا دیا کہ نہیں نہیں اس میں کوئی حرج نہیں
جس طرح سہیل کہتا ہے اسی طرح لکھ لو.چنانچہ بِاسْمِكَ اللهُمَّ کے الفاظ لکھے گئے.اس کے بعد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے.سہیل نے پھر
لے دیکھو اسد الغابہ حالات بدیل و عروه و سهیل سے زرقانی جلد دوم صفحه ۱۹۳ وابن ہشام حالات حدیبیہ
جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جاچکا ہے اس لفظ میں ادبی خوبی یہ تھی کہ لفظ سہیل اور سہل ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے
ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ بعض اوقات ناموں سے نیک فال لے لیا کرتے تھے.
Page 874
۸۵۹
ٹو کا کہ یہ رسول اللہ کا لفظ ہم نہیں لکھنے دیں گے.اگر ہم یہ بات مان لیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں تو پھر
تو یہ سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں آپ کو روکنے اور آپ کا مقابلہ کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا.بس جس طرح ہمارے ہاں طریق ہے صرف یہ الفاظ لکھو کہ محمد بن عبد اللہ نے یہ معاہدہ کیا ہے.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”آپ لوگ مانیں نہ مانیں میں خدا کا رسول تو ہوں مگر چونکہ میں محمد بن عبداللہ
بھی ہوں اس لئے چلو یہی سہی لکھو کہ "محمد بن عبداللہ نے یہ معاہدہ کیا ہے.مگر اس اثناء میں آپ
،،
کے کا تب حضرت علی معاہدہ کی تحریر میں ”محمد رسول اللہ کے الفاظ لکھ چکے تھے.آپ نے حضرت علی سے
فرما یا محمد رسول اللہ کے الفاظ مٹا دو اور ان کی جگہ محمد بن عبد اللہ کے الفاظ لکھ دو.مگر اس وقت جوش کا
عالم تھا حضرت علیؓ نے غیرت میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ ! میں تو آپ کے نام کے ساتھ سے رسول اللہ
کے الفاظ کبھی نہیں مٹاؤں گا.آپ نے ان کی از خود رفتہ حالت کو دیکھ کر فرمایا اچھا تم نہیں مٹاتے تو
مجھے دو میں خود مٹا دیتا ہوں.پھر آپ نے معاہدہ کا کاغذ (یا جو کچھ بھی وہ تھا ) ہاتھ میں لے کر اور
حضرت علیؓ سے ان الفاظ کی جگہ پوچھ کر رسول اللہ کے الفاظ اپنے ہاتھ سے کاٹ دئے اور ان کی جگہ
ابن عبد اللہ کے الفاظ لکھ دئے ہے ( حاشیہ میں نوٹ ملاحظہ فرمائیں)
بخاری کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد
: بخاری کتاب المغازی باب عمره القضاء و كتاب الصلح و مسلم باب صلح الحديبيه
نوٹ: آنحضرت کی امیت متن کی روایت میں جو بیان ہوا ہے کہ اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے ”محمد رسول اللہ کے الفاظ کاٹ کر
ان کی جگہ محمد بن عبد اللہ کے الفاظ لکھ دئے.اس پر بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال گزرسکتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم ایسی یعنی نا خواندہ تھے جیسا کہ خود قرآن شریف آپ کے متعلق اُمّی کا لفظ استعمال فرماتا ہے.تو پھر یہ کس طرح
ممکن ہوا کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کے الفاظ کاٹے اور ان کی جگہ دوسرے الفاظ لکھ دئے.اس سے پتہ لگتا
ہے کہ یا تو آپ اُمی نہیں تھے اور یا اوپر والی روایت غلط ہے.سو اس اعتراض کے متعلق کتاب ہذا کے حصہ اول میں ایک
مختصر بحث گزر چکی ہے وہ ہمارے ناظرین کی تسلی کے لئے کافی ہونی چاہئے.اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک آپ اُمّی
تھے اور جیسا کہ قرآن اور حدیث اور تاریخ کے متحدہ بیان سے ثابت ہے آپ نے کبھی بھی درسی رنگ میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا
مگر دوسری طرف یہ بھی درست ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ اُمی اور نا خواندہ تھے.چونکہ زمانہ نبوت میں آپ کے سامنے
کثرت کے ساتھ مراسلات وغیرہ پیش ہوتے رہتے تھے اس لئے اس زمانہ میں آپ کو کچھ حروف شناسی ہوگئی ہوگی اور
Page 875
۸۶۰
اس کے بعد آپ نے لکھوایا کہ معاہدہ یہ ہے کہ اہل مکہ ہمیں بیت اللہ کے طواف سے نہیں روکیں
گے.سہیل فوراً بولا خدا کی قسم اس سال تو یہ ہر گز نہیں ہو سکے گا ورنہ عربوں میں ہماری ناک کٹ جائے
گی.ہاں اگلے سال آپ لوگ آکر طواف کر سکتے ہیں.آپ نے فرمایا اچھا یہی لکھو.پھر سہیل نے اپنی
طرف سے لکھایا کہ یہ بھی شرط ہوگی کہ اہل مکہ میں سے کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ جا کر شامل نہیں ہو سکے
(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ ) ایک ذہین انسان کے لئے یہ بات ہر گز بعید از قیاس نہیں کہ وہ با وجود نا خواندہ ہونے کے
مراسلات کے بار بار سامنے آنے کی وجہ سے کچھ حروف شناسی پیدا کرلے مگر ظاہر ہے کہ ایسی حروف شناسی کے باوجود
ایسے شخص کے اُمیسی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا اور بہر حال وہ ناخواندہ ہی سمجھا جائے گا اور پھر جیسا کہ اس کتاب کے
حصہ اول میں بیان کیا جا چکا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں جو یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس موقع پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ” محمد بن عبد اللہ کے الفاظ لکھ دئے اس سے مرا دلکھا دینا ہو کیونکہ عام محاورہ میں
بعض اوقات ” لکھنے“ کا لفظ لکھا دینے کے معنی میں بھی آجاتا ہے.گویا اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ رسول اللہ
کے الفاظ تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دئے ( اور نشان دہی کے بعد ایک نا خواندہ شخص بھی آسانی کے ساتھ لکھے
ہوئے الفاظ کاٹ سکتا ہے مگر اس کے بعد ” بن عبد اللہ کے الفاظ کا تب سے لکھوا دئے اور ظاہر ہے کہ حضرت علیؓ
کی اصل غیرت ” رسول اللہ کے الفاظ کاٹنے پر تھی نہ کہ ان کی جگہ "بن عبداللہ الفاظ لکھنے پر اور حدیث میں ان
کی طرف الفاظ بھی یہی منسوب کئے گئے ہیں کہ خدا کی قسم میں رسول اللہ کے الفاظ نہیں کاٹوں گا.بہر حال
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی ہو نا قطعی طور پر ثابت ہے اور اسلام کا یہ ایک عظیم الشان علمی اور روحانی معجزہ
ہے کہ خدا کے نور نے ایک ناخواندہ انسان کو ساری قوموں اور سارے زمانوں کا معلم اور استاد بنا دیا اور آج کے
علمی زمانہ میں بھی جب کہ گویا علم کے دریا پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہے ہیں ہر بچے متلاشی اور ہر بچے محقق کی نظر
مذہب کے میدان میں ہر علمی الجھن کے موقع پر آپ کی طرف اٹھتی ہے اور وہ آپ کی ہدایت کے سوا کسی اور جگہ حقیقی
تسلی نہیں پاتا.اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ وَبَارِک وَسَلَّمْ
پھر یہ بھی یا درکھنا چاہئے کہ عربی زبان میں ایسی کے معنی نا خواندہ کے علاوہ معصوم اور پاک وصاف کے بھی ہوتے ہیں
(تاج العروس) کیونکہ امی کا لفظ دراصل ام (یعنی ماں) سے نکلا ہوا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ گناہوں اور
لغزشوں سے اس طرح بچا ہوا جس طرح ایک نوزائیدہ بچہ بچا ہوا ہوتا ہے اور یہ تعریف بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
صادق آتی ہے.: سورۃ الاعراف : : ۱۵۹،۱۵۸.نیز دیکھئے سورۃ العنکبوت
۴۹ :
Page 876
۸۶۱
گا خواہ مسلمان ہو.اور اگر ایسا کوئی شخص مسلمانوں کی طرف جائے گا تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا.صحابہ
نے اس پر شور مچایا کہ سبحان اللہ ! یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو کر آئے اور ہم اسے لوٹا
دیں.اسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ اچانک قریش مکہ کے سفیر سہیل بن عمرو کالڑ کا ابوجندل بیڑیوں اور
ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا اس مجلس میں گرتا پڑتا آپہنچا.اس نو جو ان کو اہل مکہ نے مسلمان ہونے پر قید کرلیا
تھا اور سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا.جب اسے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اس قدر
قریب تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ کسی طرح اہل مکہ کی قید سے چھوٹ کر اپنی بیٹریوں میں جکڑا ہوا گرتا
پڑتا حدیبیہ میں پہنچ گیا اور اتفاق سے پہنچا بھی اس وقت جب کہ اس کا باپ معاہدہ کی یہ شرط لکھا رہا تھا کہ
ہر شخص جو مکہ والوں میں سے مسلمانوں کی طرف آئے وہ خواہ مسلمان ہی ہو، اسے واپس لوٹا دیا جائے گا.ابو جندل نے گرتے پڑتے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے لا ڈالا اور دردناک آواز میں پکار کر کہا کہ
”اے مسلمانو! مجھے محض اسلام کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے ،خدا کے لئے مجھے بچاؤ “ مسلمان اس
نظارہ کو دیکھ کر تڑپ اٹھے مگر سہیل بھی اپنی ضد پر اڑ گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا.یہ پہلا
مطالبہ ہے جو میں اس معاہدہ کے مطابق آپ سے کرتا ہوں اور وہ یہ کہ ابوجندل کو میرے حوالہ کر دیں.آپ نے فرمایا ” ابھی تو معاہدہ تکمیل کو نہیں پہنچا.سہیل نے کہا اگر آپ نے ابو جندل کو نہ لوٹا یا تو پھر
اس معاہدہ کی کارروائی ختم سمجھیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' آؤ آؤ، جانے دو اور ہمیں
احسان ومروت کے طور پر ہی ابوجندل کو دے دو.سہیل نے کہا نہیں نہیں یہ
کبھی نہیں ہوگا.آپ نے
فرمایا سہیل ! ضد نہ کرو.میری یہ بات مان لو.سہیل نے کہا میں یہ بات ہرگز نہیں مان سکتا.اس موقع
پر ابوجندل نے پھر پکار کر کہا.اے مسلمانو! کیا تمہارا ایک مسلمان بھائی اس شدید عذاب کی حالت میں
مشرکوں کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا؟ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس وقت ابوجندل نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے اپیل نہیں کی بلکہ عامتہ المسلمین سے اپیل کی جس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ وہ جانتا تھا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہ کتنا ہی درد ہو آپ کسی صورت میں معاہدہ کی کارروائی میں
رخنہ نہیں پیدا ہونے دیں گے.مگر غالبا عامتہ المسلمین سے وہ یہ توقع رکھتا تھا کہ وہ شاید غیرت میں آکر
اس وقت جبکہ ابھی معاہدہ کی شرطیں لکھی جارہی تھیں کوئی ایسا رستہ نکال لیں جس میں اس کی رہائی کی
صورت پیدا ہو جائے مگر مسلمان خواہ کیسے ہی جوش میں تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف
بخاری کتاب الشروط
Page 877
۸۶۲
کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے.آپ نے کچھ وقت خاموش رہ کر ابوجندل سے درد مندانہ الفاظ میں
فرمایا ” اے ابوجندل ! صبر سے کام لو اور خدا کی طرف نظر رکھو.خدا تمہارے لئے اور تمہارے ساتھ کے
دوسرے کمزور مسلمانوں کے لئے ضرور خود کوئی رستہ کھول دے گا، لیکن ہم اس وقت مجبور ہیں کیونکہ
اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کی بات ہو چکی ہے اور ہم اس معاہدہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے.حضرت عمرؓ کا جوش و خروش مسلمان یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور مذہبی غیرت سے ان کی آنکھوں میں
خون اتر رہا تھا مگر رسول اللہ کے سامنے سہم کر خاموش تھے.آخر حضرت
عمر سے نہ رہا گیا.وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کا نپتی ہوئی آواز میں فرمایا ” کیا آپ
خدا کے برحق رسول نہیں ؟ آپ نے فرمایا ”ہاں ہاں ضرور ہوں.عمرؓ نے کہا ” کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارا
دشمن باطل پر
نہیں ؟ آپ نے فرمایا ”ہاں ہاں ضرور ایسا ہی ہے.‘ عمر نے کہا ” تو پھر ہم اپنے بچے دین
کے معاملہ میں یہ ذلت کیوں برداشت کریں؟“ آپ نے حضرت عمر کی حالت کو دیکھ کر مختصر الفاظ میں فرمایا
دیکھو عمر ! میں خدا کا رسول ہوں اور میں خدا کے منشا کو جانتا ہوں اور اس کے خلاف نہیں چل سکتا اور
وہی میرا مددگار ہے مگر حضرت عمرؓ کی طبیعت کا تلاطم لحظه بلحظہ بڑھ رہا تھا.کہنے لگے ” کیا آپ نے ہم
سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ”ہاں میں نے ضرور کہا تھا مگر کیا میں
نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ طواف ضرور اسی سال ہوگا ؟ عمر نے کہا ”نہیں ایسا تو نہیں کہا.آپ نے فرمایا
تو پھر انتظار کر وتم انشاء اللہ ضرور مکہ میں داخل ہو گے اور کعبہ کا طواف کرو گے مگر اس جوش کے عالم میں
حضرت عمرؓ کی تسلی نہیں ہوئی لیکن چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رعب تھا اس لئے حضرت
عمر وہاں سے ہٹ کر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی جوش کی باتیں کیں اور
حضرت ابو بکر نے بھی اسی قسم کے جواب دئے.مگر ساتھ ہی حضرت ابوبکر نے نصیحت کے رنگ میں فرمایا
”دیکھو عمر سنبھل کر ر ہوا اور رسول خدا کی رکاب پر جو ہاتھ تم نے رکھا ہے اسے ڈھیلا نہ ہو نے دو کیونکہ
خدا کی قسم یہ شخص جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہر حال سچا ہے.حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ
اس وقت میں اپنے جوش میں یہ ساری باتیں کہہ تو گیا مگر بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی اور میں تو بہ
کے رنگ میں اس کمزوری کے اثر کو دھونے کے لئے بہت سے نفلی اعمال بجا لایا ہے یعنی صدقے کئے،
روزے رکھے، نفلی نمازیں پڑھیں اور غلام آزاد کئے تا کہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے.ابن ہشام حالات صلح حدیبیہ
بخاری کتاب الشروط : ابن ہشام حالات حدیبیہ
Page 878
۸۶۳
صلح کی شرائط بہر حال بڑی ردو کر کے بعد یہ معاہدہ تکمیلکو پہنچا اور قریبا ہرامر میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنی بات کو چھوڑ کر قریش کا مطالبہ مان لیا اور خدائی منشا کے ماتحت
-1
-۲
اپنے اس عہد کو پوری وفاداری کے ساتھ پورا کیا کہ بیت اللہ کے اکرام کی خاطر قریش کی طرف سے
جو مطالبہ بھی ہوگا اسے مان لیا جائے گا اور بہر صورت حرم کے احترام کو قائم رکھا جائے گا اس معاہدہ کی
شرائط حسب ذیل تھیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سال واپس چلے جائیں یا
آئندہ سال وہ مکہ میں آکر رسم عمرہ ادا کر سکتے ہیں مگر سوائے نیام میں بند تلوار کے کوئی ہتھیار
ساتھ نہ ہوا اور مکہ میں تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں ہے
اگر کوئی مرد مکہ والوں میں سے مدینہ جائے تو خواہ وہ مسلمان ہی ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے
مدینہ میں پناہ نہ دیں اور واپس لوٹا دیں.چنانچہ اس تعلق میں صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ
لَا يَاتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا یعنی ”ہم میں سے اگر کوئی مرد
آپ کے پاس جائے تو آپ اسے واپس لوٹا دیں گے.“
لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ کو چھوڑ کر مکہ میں آجائے تو اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا.اور ایک
روایت میں یہ ہے کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی شخص اپنے ولی یعنی گارڈین کی اجازت کے بغیر مدینہ
آجائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا.-
له
قبائل عرب میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہے اہل مکہ کا.یہ معاہدہ فی الحال دس سال تک کے لئے ہوگا اور اس عرصہ میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان
: بخاری کتاب الشروط وکتاب الصلح
بخاری کتاب المغازی باب عمرة القضا و کتاب الجہاد باب المصالحته على ثلاثة ايام وكتاب الصلح باب الصلح مع
المشركين و مسلم باب صلح الحديبيه
بخاری کتاب الشروط اور کتاب المغازی حالات حدیبیہ حدیث عن مروان و مسور
بخاری کتاب الصلح باب الصلح مع المشرکین.مسلم باب صلح الحدیبین انس وابن سعد حالات حدیبیہ
۵ سيرة ابن هشام
ابن ہشام وابن سعد و طبری
Page 879
۸۶۴
جنگ بندر ہے گی یا
اس معاہدہ کی دو نقلیں کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے ان پر دستخط ثبت کئے.مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمان ( جو اس
وقت تک مکہ سے واپس آچکے تھے ) عبد الرحمن بن عوف ، سعد بن ابی وقاص اور ابوعبیدہ تھے.معاہدہ
کی تکمیل کے بعد سہیل بن عمر و معاہدہ کی ایک نقل لے کر مکہ کی طرف واپس لوٹ گیا اور دوسری نقل
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی.صحابہ میں اضطراب جب سہیل واپس جاچکا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ
لواب اٹھو اور یہیں اپنی قربانیاں ذبح کر کے سروں کے بال منڈوا دو
( قربانی کے بعد سر کے بالوں کو منڈوایا یا کتر وایا جاتا ہے ) اور واپسی کی تیاری کرو.مگر صحابہ کو اس بظاہر
رسوا کن معاہدہ کی وجہ سے سخت صدمہ تھا اور ساتھ ہی جب انہیں اس طرف خیال جاتا تھا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک خواب کی بنا پر یہاں لائے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں طواف بیت اللہ کا
نظارہ بھی دکھایا تھا تو ان کی طبیعت بہت ہی مضمحل ہونے لگتی تھی اور وہ قریباً بے جانوں کی طرح بے حس
وحرکت پڑے تھے.انہیں خدا کے رسول پر پورا پورا ایمان تھا اور اس کے وعدہ پر بھی کامل یقین تھا مگر
لوازمات بشریت کے ماتحت ان کے دل اس ظاہری ناکامی پر غموں سے نڈھال تھے اس لئے جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ اب یہیں قربانی کے جانور ذبح کر دو اور واپس لوٹ چلو تو
کسی صحابی نے سامنے سے حرکت نہ کی.اس لئے نہیں کہ وہ نعوذ باللہ اپنے رسول کے نافرمان تھے کیونکہ
صحابہ سے بڑھ کر دنیا کے پردے پر کوئی فرمانبردار جماعت نہیں گزری.پس ان کی طرف سے یہ عدم تعمیل
بغاوت یا نا فرمانی کے رنگ میں نہ تھی بلکہ اس لئے تھی کہ غم اور ظاہری ذلت کے احساس نے انہیں اتنا
نڈھال کر رکھا تھا کہ وہ گویا سنتے ہوئے نہ سنتے تھے اور دیکھتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں کام نہ کرتی
تھیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کو دوبارہ سہ بارہ دہرایا مگر کسی صحابی نے سامنے سے
حرکت نہ کی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ ہوا اور آپ خاموش ہو کر اپنے خیمہ کے اندر تشریف
ابوداؤ د کتاب الجہاد باب فی صلح العد و وابن ہشام وابن سعد : ابن سعد وزرقانی
ملاحظہ ہو کہ با وجود سخت اختلاف رائے کے حضرت عمر دستخط کرنے میں قطعا متائل نہیں ہوئے
ابن ہشام
۵: ابن سعد و طبری و زرقانی
Page 880
۸۶۵
لے گئے.اندرون خیمہ آپ کی حرم محترم حضرت ام سلمہ جو ایک نہایت زیرک خاتون تھیں یہ سارا نظارہ
دیکھ رہی تھیں.انہوں نے اپنے موقر اور محبوب خاوند کو فکر مند حالت میں اندر آتے دیکھا اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے آپ کے فکر و تشویش کی تفاصیل معلوم کیں تو ہمدردی اور محبت کے انداز میں
عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ رنج نہ فرمائیں آپ کے صحابہ خدا کے فضل سے نافرمان نہیں.مگر اس صلح کی
شرائط نے انہیں غم سے دیوانہ بنا رکھا ہے.پس میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے کچھ نہ فرما ئیں بلکہ خاموشی
کے ساتھ باہر جا کر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح فرما دیں اور اپنے سر کے بالوں کو منڈ اود میں پھر آپ کے
صحابہ خود بخود آپ کے پیچھے ہو لیں گے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ نے باہر
تشریف لا کر بغیر کچھ کہے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اپنے سر کے بال منڈوانے شروع کر دئے.صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو جس طرح ایک سویا ہوا شخص کوئی شور وغیرہ بن کر اچانک بیدار ہوتا ہے وہ چونک کر
اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے کے سر کے بال
مونڈنے لگے مگر غم نے اس قدر بے چین کر رکھا تھا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ اس وقت ایسا عالم تھا کہ ڈر
تھا کہ مسلمان کہیں ایک دوسرے کے بال مونڈ تے مونڈتے ایک دوسرے کا گلا ہی نہ کاٹ دیں لے
بہر حال حضرت ام سلمہ کی تجویز کارگر ہوئی اور جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ
وقتی طور پر ناکام رہے تھے آپ کے عمل نے سوتے ہوؤں کو چونکا کر بیدار کر دیا.یبیہ سے واپسی اور سورۃ فتح کا نزول قربانی وغیرہ سے فارغ ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے مدینہ کی طرف واپسی کا حکم دیا.اس وقت آپ کو
حدیبیہ میں آئے کچھ کم ہیں یوم ہو چکے تھے.جب آپ واپسی سفر میں عسفان کے قریب کراع النعمیم میں
پہنچے اور یہ رات کا وقت تھا تو اعلان کرا کے صحابہ کو جمع کروایا اور فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک سورۃ نازل
بخاری کتاب الشروط وزرقانی
ہے : اس موقع پر اکثر صحابہ نے تو اپنے سر کے بال منڈوا دیئے تھے مگر بعض نے صرف کتروانے پر اکتفا کی تھی.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوانے والوں کو مکر رسہ مکر رد عادی.لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ آپ نے منڈوانے والوں
کو تین دفعہ دعا دی ہے اور کتروانے والوں کے لئے صرف ایک دفعہ دعائیہ الفاظ فرمائے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس
کی وجہ یہ ہے کہ بال منڈوانے والے لوگ وہ ہیں جو اس وقت شک میں مبتلا نہیں ہوئے مگر بال کتر وانے والے شک میں
مبتلا ہو گئے.ابن ہشام
Page 881
۸۶۶
ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور وہ یہ ہے:
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا نَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَان وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَصْرًا
عَزِيزًا...لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
إِنْ شَاءَ اللهُ أَمِنِيْنَ مُحَلِقِيْنَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لَا تَخَافُونَ
یعنی اے رسول! ہم نے تجھے ایک عظیم الشان فتح عطا کی ہے تا کہ ہم تیرے لئے ایک
ایسے دور کا آغاز کرا دیں جس میں تیری انگلی اور پچھلی سب کمزوریوں پر مغفرت کا پردہ پڑ جائے
اور تا خدا اپنی نعمت کو تجھ پر کامل کرے اور تیرے لئے کامیابی کے سیدھے رستے کھول دے
اور ضرور خدا تعالیٰ تیری زبر دست نصرت فرمائے گا.حق یہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کی اس
خواب کو پورا کر دیا جو اس نے رسول کو دکھائی تھی.کیونکہ اب تم انشاء اللہ ضرور ضرور امن کی
حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو گے اور قربانیوں کو خدا کی راہ میں پیش کر کے اپنے سر کے
بالوں کو منڈواؤ گے یا کتر واؤ گے اور تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا ، یعنی اگر تم اس سال مکہ میں
داخل ہو جاتے تو یہ داخلہ امن کا نہ ہوتا بلکہ جنگ اور خون ریزی کا داخلہ ہوتا مگر خدا نے
خواب میں امن کا داخلہ دکھایا تھا اس لئے خدا نے اس سال معاہدہ کے نتیجہ میں امن کی
صورت پیدا کر دی اور اب عنقریب تم خدا کی دکھائی ہوئی خواب کے مطابق امن کی حالت میں
مسجد حرام میں داخل ہو گے.چنانچہ ایسا ہی ہوا.جب آپ نے یہ آیات صحابہ کوسنا ئیں تو چونکہ بعض صحابہ کے دل میں ابھی تک صلح حدیبیہ کی تلخی باقی تھی
وہ حیران ہوئے کہ ہم تو بظاہر نا کام ہو کر واپس جارہے ہیں اور خدا ہمیں فتح کی مبارک باد دے رہا ہے حتی
که بعض جلد باز صحابہ نے اس قسم کے الفاظ بھی کہے کہ کیا یہ فتح ہے کہ ہم طواف بیت اللہ سے محروم ہوکر
واپس جارہے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور
ایک مختصری تقریر میں جوش کے ساتھ فرمایا یہ بہت بیہودہ اعتراض ہے کیونکہ غور کیا جائے تو واقعی حدیبیہ کی
صلح ہمارے لئے ایک بڑی بھاری فتح ہے.قریش جو ہمارے خلاف میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے
انہوں نے خود جنگ کو ترک کر کے امن کا معاہدہ کر لیا ہے اور آئندہ سال ہمارے لئے مکہ کے دروازے
لف
ل : سورۃ اصح : ۲ تا ۴
: سورة الفتح : ١٨ ۲۸
Page 882
۸۶۷
کھول دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہم امن وسلامتی کے ساتھ اہل مکہ کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ ہو کر آئندہ
فتوحات کی خوشبو پاتے ہوئے واپس جارہے ہیں.پس یقیناً یہ ایک عظیم الشان فتح ہے.کیا تم لوگ ان
نظاروں کو بھول گئے کہ یہی قریش اُحد اور احزاب کی جنگوں میں کس طرح تمہارے خلاف چڑھائیاں کرکر
کے آئے تھے.اور یہ زمین با وجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تمہاری آنکھیں پتھر اگئی تھیں اور کلیجے
منہ کو آتے تھے مگر آج یہی قریش تمہارے ساتھ امن و امان کا معاہدہ کر رہے ہیں.صحابہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ ! ہم سمجھ گئے.ہم سمجھ گئے.جہاں تک آپ کی نظر پہنچی ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچتی
مگر اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ معاہدہ ہمارے لئے ایک بھاری فتح ہے.حضرت عمر کا مزید پیچ و تاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر سے پہلے حضرت عمر بھی
بڑے بیچ و تاب میں تھے.چنانچہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کی
واپسی پر جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سفر میں تھے تو اس وقت میں آپ کی خدمت
میں حاضر ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کچھ عرض کرنا چاہا مگر آپ خاموش رہے.میں
نے دوبارہ.سہ بارہ عرض کیا مگر آپ بدستور خاموش رہے..مجھے آنحضرت کی اس خاموشی پر بہت غم ہوا
اور میں اپنے نفس میں یہ کہتا ہوا کہ عمر تو تو ہلاک ہو گیا کہ تین دفعہ تو نے رسول اللہ کو مخاطب کیا مگر آپ نہیں
بولے چنانچہ میں مسلمانوں کی جمعیت میں سے سب سے آگے نکل آیا اور اس غم میں پیچ و تاب کھانے لگا کہ
کیا بات ہے؟ اور مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی قرآنی آیت نازل نہ ہو جائے.اتنے
میں
کسی شخص نے میرا نام لے کر آواز دی کہ عمر بن خطاب کو رسول اللہ نے یا دفرمایا ہے.میں نے کہا بس
ہونہ ہو میرے متعلق کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی ہے.چنانچہ میں گھبرایا ہوا جلدی جلدی رسول اللہ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے آپ کے پہلو میں آگیا.آپ نے فرمایا ”مجھ پر اس وقت ایک
ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے.پھر آپ نے سورہ فتح کی
آیات تلاوت فرما ئیں.سے حضرت عمرؓ نے عرض کیا.یا رسول اللہ! کیا یہ صلح واقعی اسلام کی فتح ہے؟ آپ
نے فرمایا ہاں یقیناً یہ ہماری فتح ہے.اس پر حضرت عمرؓ تسلی پا کر خاموش ہو گئے.اس کے بعد
غالباً اس وقت سورۃ فتح کی آیات نازل ہورہی ہوں گی
ے بہیقی بحوالہ زرقانی جلد دوم صفحه ۲۱ ۲۱۱
: بخاری کتاب
التفسير باب تفسير سورة فتح وكتاب المغازي عن زيد بن اسلم عن ابيه
: مسلم باب صلح الحدیبیہ عن انس
Page 883
ΔΥΛ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس تشریف لے آئے.مسلمان مہاجر عورتوں کے لئے ایک استثنائی انتظام معاہدوں میں رخنے رہ جایا کرتے
ہیں جو بعض اوقات بعد میں اہم نتائج
کا باعث بن جاتے ہیں.چنانچہ صلح حدیبیہ میں بھی یہ رخنہ رہ گیا تھا کہ اس میں گومسلمان مردوں کی واپسی
کے متعلق صراحتاً ذکر تھا مگر ایسی عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا جو اہل مکہ میں سے اسلام قبول کر کے مسلمانوں
میں آملیں.مگر جلد ہی ایسے حالات رونما ہونے لگے جن سے کفار مکہ پر اس رخنہ کا وجود کھلے طور پر ظاہر
ہو گیا.چنانچہ ابھی اس معاہدہ پر بہت تھوڑا وقت گزرا تھا کہ مکہ سے بعض مسلمان عورتیں کفار کے ہاتھ سے
چھٹ کر مدینہ میں پہنچ گئیں.ان میں سب سے اول نمبر پر مکہ کے ایک فوت شدہ مشرک رئیس عقبہ ابن ابی
معیط کی لڑکی ام کلثوم تھی جو ماں کی طرف سے حضرت عثمان بن عفان کی بہن بھی لگتی تھی.ام کلثوم بڑی ہمت
دکھا کر پا پیادہ مدینہ پہنچی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اظہار
کیا.مگر اس کے پیچھے پیچھے اس کے دو قریبی رشتہ دار بھی اس کے پکڑنے کے لئے پہنچ گئے اور اس کی واپسی
کا مطالبہ کیا.ان لوگوں کا دعوی یہ تھا کہ ( گو معاہدہ میں مرد کا لفظ استعمال ہوا ہے مگر ) دراصل معاہدہ عام
ہے اور عورت مرد دونوں پر مساوی اثر رکھتا ہے.مگر اُم کلثوم معاہدہ کے الفاظ کے علاوہ اس بنا پر بھی عورتوں
کے معاملہ میں استثنا کی مدعی تھی کہ عورت ایک کمز ور جنس سے تعلق رکھتی ہے اور ویسے بھی وہ مرد کے مقابلہ
پر ایک ماتحت پوزیشن میں ہوتی ہے اس لئے اسے واپس کرنا گویا روحانی موت کے منہ میں دھکیلنا اور
اسلام سے محروم کرنا ہے.پس عورتوں کا اس معاہدہ سے منتقلی سمجھا جانا نہ صرف عین معاہدہ کے مطابق
بلکہ عقلاً بھی قرین انصاف اور ضروری تھا اس لئے طبعا اور انصافاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم
کے حق میں فیصلہ فرمایا اور اس کے رشتہ داروں کو واپس لوٹا دیا اور خدا تعالیٰ نے بھی اس فیصلہ کی تائید
فرمائی چنانچہ انہی دنوں میں یہ قرآنی آیات نازل ہوئیں کہ جب کوئی عورت اسلام کا ادعا کرتی ہوئی مدینہ
میں آئے تو اس کا اچھی طرح سے امتحان کرو اور اگر وہ نیک بخت اور مخلص ثابت ہو تو پھر ا سے کفار کی طرف
ہرگز نہ لوٹاؤ لیکن اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کا مہر اس کے مشرک خاوند کوضرور ادا کر دو.اس کے بعد
جب بھی کوئی عورت مکہ سے نکل کر مدینہ میں پہنچتی تھی تو اس کا اچھی طرح سے امتحان لیا جا تا تھا اور اس کی
اسد الغابہ حالات ام كلثوم وسيرة حلبيه حالات حديبيه
: سيرة حلبیہ جلد ۳ صفحه ۲۹
:۳ قرآن شریف سورة الممتحنہ : ۱۱ و بخاری وغیرہ
Page 884
۸۶۹
نیت اور اخلاص کو اچھی طرح پر کھا جاتا تھا.پھر جو عورتیں نیک نیت اور مخلص ثابت ہوتی تھیں اور ان کی
ہجرت میں کوئی دنیوی یا نفسانی غرض نہیں پائی جاتی تھی تو انہیں مدینہ میں رکھ لیا جاتا تھا اور اگر وہ شادی شدہ
ہوتی تھیں تو ان کا مہران کے خاوندوں کو ادا کر دیا جاتا تھا.اس کے بعد وہ مسلمانوں میں شادی کرنے
کے لئے آزاد ہوتی تھیں.مشرک عورتوں کو بھی آزاد کر دیا گیا جہاں ایک طرف مسلمان عورتوں کے لئے یہ خاص صورت
تجویز کی گئی وہاں دوسری طرف اس موقع پر مشرک عورتوں
کے متعلق بھی یہ خاص احکام جاری ہوئے کہ اگر کوئی مشرک عورت مسلمانوں کے نکاح میں ہو تو مسلمان
اسے آزاد کر دیں اور آئندہ کے لئے یہ حکم نافذ کیا گیا کہ کوئی مشرک عورت کسی مسلمان مرد کے نکاح میں
نہیں رہ سکتی.یہ احکام بھی قرآن شریف کے ذریعہ نازل ہوئے کیے اور ان آیات کے نزول کے بعد حضرت
عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے جن کے نکاح میں اس وقت تک بعض مشرک عورتیں تھیں اپنی مشرک
بیویوں کو طلاق دے کر آزاد کر دیا.کے اس ضمن میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام نے ہر غیر مسلم عورت
کے ساتھ نکاح منع نہیں کیا بلکہ صرف مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح منع کیا ہے اور اہل کتاب عورتوں
کے ساتھ نکاح جائز رکھا ہے.ان احکام میں مصلحت یہ ہے کہ:
اول : تو مشرک کا مذہب اسلام سے بعید ترین ہے اور دونوں کے درمیان کوئی اتصال کی کڑی نہیں
ہے اور ایک مشرک عورت کے ساتھ نکاح میں یہ اندیشہ ہے کہ اس کی تربیت میں اولا د دین کے
مبادی سے ہی بے بہرہ رہے.دوسرے : ایک مشرک انسان کا کوئی ضابطہ اخلاق معین نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلقات
کبھی بھی کسی معین اور مستحکم بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتے.دوسری طرف خاص حالات میں تعلقات کی
توسیع کی گنجائش کا رکھا جانا بھی ضروری تھا.پس مشرک عورتوں سے نکاح حرام قرار دے کر باقی
غیر مسلم عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئی.دنیا کے موجودہ مذاہب میں سے عیسائی،
یہودی، ہندو وغیرہ اہل کتاب کی اصطلاح میں داخل ہیں.جن سے ایک مسلمان کا رشتہ ہوسکتا
:
بخاری حالات حدیبیه و باب تفسیر سورۃ الممتحنه و باب صلح الحدیبیہ نیز طبری حالات حدیبیه صفحه ۱۵۵۳ وابن جریر
جلد ۲۸ صفحه ۴۴، ۴۵ و اسد الغا به حالات ام کلثوم
قرآن شریف سورة الممتحنه : ۱۱
سے : بخاری کتاب التفسیر باب تفسیر سورة الممتحنه وتفسیر ابن کثیر وطبری : قرآن شریف سورة الممتحنه : ۱۱
Page 885
۸۷۰
ہے.البتہ افریقہ وغیرہ کی اکثر وحشی اقوام اہل کتاب میں سے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ رشتہ
ہر صورت میں ممنوع ہے.چونکہ اس مسئلہ میں کسی قدر مفصل بحث او پر گزرچکی ہے اس لئے اس جگہ
اسی قدر مختصر نوٹ پر اکتفا کی جاتی ہے.ابوبصیر کا واقعہ اور اس کے نتائج معاہدہ حدیبیہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر قریش
میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف آوے تو مدینہ
والے اسے پناہ نہیں دیں گے بلکہ واپس لوٹا دیں گے لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام سے منحرف ہو کر مکہ کا رخ
کرے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے.بظاہر یہ شرط مسلمانوں کے لئے موجب ہتک سمجھی گئی تھی
اور اسی لئے کئی مسلمان اس پر دل برداشتہ تھے.حتی کہ حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر اور فہیم صحابی کو بھی اس
وقت کی برق زدہ فضا میں اس شرط پر ناراضگی اور بے چینی پیدا ہوئی تھی مگر اس کے بعد جلد ہی ایسے حالات
پیدا ہو گئے جن سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ دراصل یہ شرط قریش کے لئے کمزوری کا باعث اور
مسلمانوں کی مضبوطی کا موجب تھی.کیونکہ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی فرما دیا تھا
اگر کوئی مسلمان مدینہ سے منحرف ہو کر جائے گا تو وہ ایک گندہ عضو ہوگا جس کا کاٹا جانا ہی بہتر تھا لیکن اس
کے مقابل پر اگر کوئی شخص سچے دل سے مسلمان ہو کر مکہ سے نکلے گا تو خواہ اسے مدینہ میں جگہ ملے یا نہ ملے وہ
جہاں بھی رہے گا اسلام کی مضبوطی کا باعث ہوگا اور بالآخر اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی رستہ کھول دے گا.اس نظریہ نے جلد ہی اپنی صداقت کو ثابت کر دیا.کیونکہ ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف
لائے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک شخص ابو بصیر عتبہ بن اسید ثقفی جو مکہ کا رہنے والا تھا اور قبیلہ بنوزہرہ
کا حلیف تھا مسلمان ہو کر اور مکہ والوں کی حراست سے بھاگ کر مدینہ پہنچا.قریش مکہ نے اس کے پیچھے
پیچھے اپنے دو آدمی بھجوائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ ابو بصیر کو معاہدہ کی شرائط کے مطابق
ان کے حوالہ کر دیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو بلایا اور واپس چلے جانے کا حکم دیا.ابوبصیر نے
سامنے سے واویلا کیا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ لوگ مجھے مکہ میں تنگ کریں گے اور اسلام سے منحرف ہو جانے
کے لئے جبر سے کام لیں گے.آپ نے فرمایا ”ہم معاہدہ کی وجہ سے معذور ہیں اور تمہیں یہاں نہیں
رکھ سکتے اور اگر تم خدا کی رضا کی خاطر صبر سے کام لو گے تو خدا خود تمہارے لئے کوئی رستہ کھول دے گا
مگر ہم مجبور ہیں اور کسی صورت میں معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے.“ نا چا را بو بصیر ان لوگوں کے
ل : مسلم بحوالہ زرقانی جلد ۲ صفحہ ۱۹۹
Page 886
۸۷۱
ساتھ واپس روانہ ہو گیا مگر چونکہ اس کے دل میں اس بات کی سخت دہشت تھی کہ مکہ میں پہنچ کر اس پر طرح
طرح کے ظلم ڈھائے جائیں گے اور اسے اسلام جیسی نعمت کو چھپا کر رکھنا پڑے گا بلکہ شاید جبر وتشد د کی وجہ
سے اس سے ہاتھ ہی دھونا پڑے.اس لئے جب یہ پارٹی ذوالحلیفہ میں پہنچی جو مدینہ سے چند میل کے
فاصلہ پر مکہ کے رستے پر ہے تو ابو بصیر نے موقع پا کر اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو جو اس پارٹی کا رئیس تھا
قتل کر دیا اور قریب تھا کہ دوسرے کو بھی نشانہ بنائے مگر وہ اپنی جان بچا کر اس طرح بھا گا کہ ابو بصیر سے
پہلے مدینہ پہنچ گیا.پیچھے پیچھے ابو بصیر بھی مدینہ میں آپہنچا.جب یہ شخص مدینہ میں پہنچا تو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے.اس کی خوف زدہ حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا.معلوم ہوتا
ہے اسے کوئی خوف و ہراس کا سخت دھکا لگا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود بھی ہانپتے ہانپتے آپ سے
عرض کیا کہ ”میرا ساتھی مارا گیا ہے اور میں بھی گویا موت کے منہ میں ہوں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس سے واقعہ سنا اور تسلی دی.اتنے میں ابو بصیر بھی ہاتھ میں تلوار تھامے آن پہنچا اور آتے ہی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے قریش کے حوالے کر دیا اور آپ کی
ذمہ داری ختم ہوگئی مگر مجھے خدا نے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے اور اب آپ پر میری کوئی ذمہ داری
نہیں.“ آپ نے بے ساختہ فرمایا:
وَيْلُ أُمِّهِ مُسْعِرُ حَرُبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ
یعنی اس کی ماں کے لئے خرابی ہو ( یہ الفاظ عربوں کے محاورہ میں لفظی معنوں کو نظر انداز
کرتے ہوئے ملامت یا تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں ) یہ شخص تو جنگ کی آگ بھڑ کا رہا
ہے کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہو.ابوبصیر نے یہ الفاظ سنے تو سمجھ لیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہر حال معاہدہ کی وجہ سے
واپس جانے کا ارشاد فرمائیں گے.چنانچہ اس بارے میں بخاری کے الفاظ یہ ہیں:
فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ -
لے : اس کا دوسری طرف جانے کی بجائے مدینہ کی طرف آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ
میرے لئے مدینہ ایک محفوظ جگہ ہے اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہر حال اس کی حفاظت فرمائیں گے اور کسی صورت
میں معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی.بخاری کتاب الشروط وابوداؤ د كتاب الجها دباب في الصلح العدو
بخاری کتاب الشروط
Page 887
۸۷۲
یعنی ” جب ابو بصیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو جان لیا کہ آپ
بہر حال اسے مکہ والوں کی طرف واپس بھجوا دیں گے.“
اس پر وہ چپکے سے وہاں سے نکل آیا اور مکہ جانے کی بجائے جہاں اسے جسمانی اور روحانی دونوں
موتیں نظر آتی تھیں بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف ہٹ کر سیف البحر میں پہنچ گیا.جب مکہ کے دوسرے مخفی اور کمزور مسلمانوں کو یہ علم ہوا کہ ابوبصیر نے ایک علیحدہ ٹھکانا بنالیا ہے تو وہ
بھی آہستہ آہستہ مکہ سے نکل نکل کر سیف البحر میں پہنچ گئے.انہی لوگوں میں رئیس مکہ سہیل بن عمرو کا لڑکا
ابو جندل بھی تھا جس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیبیہ سے واپس لوٹا
دیا تھا.آہستہ آہستہ ان لوگوں کی تعداد ستر کے قریب یا بعض روایات کے مطابق تین سو تک پہنچ گئی.اور اس طرح گویا مدینہ کے علاوہ ایک دوسری اسلامی ریاست بھی معرض وجود میں آگئی جو مذ ہبا تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت تھی مگر سیاست جدا اور آزاد تھی.چونکہ ایک طرف حجاز کی حدود میں ایک
علیحدہ اور آزاد سیاسی نظام کا موجود ہونا قریش کے لئے خطرہ کا باعث تھا اور دوسری طرف سیف البحر کے
مہاجر قریش مکہ سے سخت زخم خوردہ تھے اس لئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ان مہاجرین سیف البحر
اور قریش کے تعلقات نے قریباً قریباً وہی صورت اختیار کر لی جو ابتدا میں مہاجرین مدینہ کے متعلق پیدا
ہوئی تھی اور چونکہ سیف البحر اس رستہ کے بالکل قریب تھا جو مدینہ سے شام کو جاتا تھا اس لئے قریش کے
قافلوں کے ساتھ ان مہاجرین کی مٹھ بھیڑ ہونے لگی.اس نئی جنگ نے جلد ہی قریش کے لئے خطرناک
صورت اختیار کر لی کیونکہ اول تو قریش سابقہ جنگ کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے اور دوسرے اب وہ پہلے کی
نسبت تعداد میں بھی بہت کم تھے اور ان کے مقابل پر سیف البحر کی اسلامی ریاست جو ابو بصیر اور ابوجندل
جیسے جان فروشوں کی کمان میں تھی.ایمان کے تازہ جوش اور اپنے گزشتہ مظالم کی تلخ یاد میں اس برقی
طاقت سے معمور تھی جو کسی مقابلہ کو خیال میں نہیں لاتی.نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصہ میں ہی قریش نے ہتھیار
ڈال دئے اور ابو بصیر کی پارٹی کے حملوں سے تنگ آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک
سفارت کے ذریعہ درخواست کی اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر عرض کیا کہ سیف البحر کے مہاجرین کو
مدینہ میں بلا کر اپنے سیاسی انتظام میں شامل کرلیں اور ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کی
لے: ابن ہشام
سہیلی شرح ابن ہشام و موسیٰ بن عقبہ بحوالہ زرقانی
Page 888
۸۷۳
اس شرط کو کہ مکہ کے نومسلموں
کو مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی اپنی خوشی سے منسوخ کر دیا.آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فرمالیا اور ابو بصیر اور ابو جندل کو ایک خط کے ذریعہ اطلاع بھجوائی
کہ چونکہ قریش نے اپنی خوشی سے معاہدہ میں ترمیم کر دی ہے اس لئے اب انہیں مدینہ میں چلے آنا چاہئے
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اینچی سیف الحر پہنچا تو اس وقت ابوبصیر بیمار ہوکر صاحب فراش تھا اور
حالت نازک ہورہی تھی.ابو بصیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کو بڑے شوق کے ساتھ
اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا اور تھوڑی دیر بعد اسی حالت میں جان دے دی اور اس کے بعد ا بو جندل اور
اس کے ساتھی اپنے اس باہمت اور جوانمبر دامیر کو سیف البحر میں ہی دفن کر کے خوشی اور غم کے مخلوط جذبات
کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے.غم اس لئے کہ ان
کا بہادر لیڈ رابوبصیر جو
اس واقعہ کا ہیرو تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی سے محروم رہا اور خوشی اس بات پر کہ وہ خود
اپنے آقا کے قدموں میں پہنچ گئے اور قریش کے خونی مقابلہ سے نجات ملی.ابوبصیر اور ان کے رفقا کا دلچسپ کا رنامہ صلح حدیبیہ کے معا بعد سے لے کر کئی ماہ کے وقفہ پر پھیلا
ہوا تھا اور اس عرصہ میں بعض دوسرے واقعات بھی پیش آئے.مگر ہم نے صلح حدیبیہ سے تعلق رکھنے والے
واقعات کو یکجا بیان کرنے کی غرض سے اسے صلح حدیبیہ کے ساتھ ہی بیان کر دیا ہے.صلح حدیبیہ کے تعلق میں عیسائی مؤرخین کے دواعتراضات غالباً آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی سوانح کا کوئی
اہم واقعہ ایسا نہیں ہے جسے مسیحی مؤرخین نے بغیر اعتراض کے چھوڑا ہو اور صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی اسی کلیہ
کے نیچے آتا ہے.بعض ضمنی اور غیر اہم اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے عیسائی مصنفین نے صلح حدیبیہ
کے تعلق میں دو اعتراض کئے ہیں:
اول : یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی شرائط سے عورتوں کو مستثنی قرار دیا یہ شرائط
معاہدہ کی رو سے جائز نہیں تھا کیونکہ معاہدہ کے الفاظ عام تھے جس میں مرد عورت سب شامل تھے.دوم یہ کہ ابو بصیر کے واقعہ کے تعلق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی روح کو توڑا بلکہ
ابو بصیر کو یہ اشارہ دے کر کہ وہ مکہ میں واپس جانے کی بجائے ایک الگ پارٹی بنا کر اپنا کام کرسکتا ہے
بخاری کتاب الشروط وابن ہشام وطبری و تاریخ شمس وسيرة حلبیہ
: زرقانی جلد ۲ صفحه ۲۰۳ و تاریخ خمیس
Page 889
۸۷۴
اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی.ان اعتراضوں کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہئے کہ یہ معاہدہ قریش مکہ کے
ساتھ ہوا تھا اور قریش مکہ وہ قوم تھی جو ابتدائے اسلام سے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
برسر پیکار چلی آتی تھی اور بات بات پر اعتراض کرنے اور طعنہ دینے کی عادی تھی اور ویسے بھی وہ کوئی
دور دراز کی غیر قوم نہ تھی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی قوم تھی جسے سب حالات کا پورا پوراعلم تھا
اور پھر شرائط معاہدہ کی تمام تفصیلات اور ان کا مکمل پس منظر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھا.پس جب مکہ
کے قریش نے جو فریق معاہدہ تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر اعتراض نہیں کیا اور اسے معاہدہ
کے خلاف نہیں سمجھا تو تیرہ سو سال بعد میں آنے والے لوگوں کو جن کی آنکھوں سے بہت سی جز کی تفاصیل
پوشیدہ ہیں اور انہیں اس معاہدہ کے پس منظر پر بھی پوری طرح آگا ہی نہیں اعتراض کا حق کس طرح پیدا
ہوسکتا ہے؟ یہ تو مدعی ست گواہ چست والا معاملہ ہوا کہ جن کے ساتھ یہ سارا قصہ گزرا ہے.وہ تو اسے درست
قرار دے کر خاموش رہتے ہیں مگر تیرہ سو سال بعد میں آنے والوں نے گویا آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے.آخر
یہ کیا وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن وحدیث اور عرب کی تاریخ ان اعتراضوں سے بھرے پڑے ہیں
جو کفار مکہ اور دوسرے کفار عرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے مگر یہ ذکر
کسی جگہ نہیں آتا کہ مسلمانوں پر صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہو.علاوہ ازیں یہ بات مضبوط ترین شہادت سے ثابت ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی طرف تبلیغی خط ارسال کیا اور اس وقت اتفاق سے ابوسفیان بن حرب
رئیس مکہ بھی شام میں گیا ہوا تھا اور ہر قل شہنشاہ روم نے اسے اپنے دربار میں بلا کر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے متعلق بعض سوالات کئے جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ” کیا تمہاری قوم کے اس
مدعی نبوت نے کبھی کسی معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ابوسفیان نے جو
اس وقت رأس المنکرین اور اسلام کا اشد ترین دشمن تھا جو الفاظ کہے وہ یہ تھے.لا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِى مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيْهَا وَلا يُمْكِنُنِي كَلِمَةً اَدْخُلُ فِيْهَا شَيْئًا
غَيْرَهذِهِ الْكَلِمَةِ
یعنی نہیں.محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے کبھی کسی معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی ہاں آج
بخاری باب کیف کان بدا الوحی
Page 890
۸۷۵
کل اس کے ساتھ ہمارے ایک معاہدہ کی میعاد چل رہی ہے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس معاہدہ
کے اختتام تک اس کی طرف سے کیا امر ظاہر ہو.ابوسفیان کہتا ہے کہ اس ساری گفتگو میں
میرے لئے اس فقرہ کے بڑھا دینے کے سوا کوئی اور موقع نہیں تھا کہ میں آپ کے خلاف ہر قل
کے دل میں کوئی امکانی شبہ پیدا کر سکوں.“
ابوسفیان اور ہر قل کی یہ گفتگو صلح حدیبیہ کے معابعد نہیں ہوئی تھی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف سے ہر قل کے نام تبلیغی خط تیار کر کے روانہ کرنے اور پھر اس خط کے ہرقل تک پہنچنے اور پھر ہر قل کی
طرف سے دربار منعقد ہونے اور ابو سفیان کو تلاش کر کے اپنے دربار میں بلانے وغیرہ میں لازماً وقت لگا
ہوگا اور قرین قیاس یہ ہے کہ اس وقت تک ابو بصیر کے مدینہ میں بھاگ آنے اور اُم کلثوم وغیرہ مسلمان
عورتوں کے مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچ جانے کے واقعات ہو چکے ہوں گے.اسی لئے سب مؤرخ ابو بصیر اور
اُم کلثوم والے واقعہ کو پہلے اور قیصر روم والے خط کے واقعہ کو اس کے بعد بیان کرتے ہیں مگر با وجود
اس کے ابوسفیان ہرقل کے دربار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد شکنی کا الزام نہیں لگا سکا
حالانکہ اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کی یہ خواہش تھی کہ اگر کوئی ہاتھ پڑ سکے تو دریغ نہ کروں مگر باوجوداس
کے تیرہ سوسال بعد میں پیدا ہونے والے نقاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عہد شکنی کا الزام لگاتے ہوئے
خدا کا خوف محسوس نہیں کرتے.افسوس صد افسوس!
پھر اگر ان اعتراضوں کی تفصیل میں جائیں تو ان کا بودا پن اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے مثلاً
پہلا اعتراض یہ ہے کہ دراصل معاہدہ میں مرد اور عورتیں دونوں شامل تھیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے زبر دستی سے کام لے کر عورتوں کو مستثنیٰ قرار دے دیا لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ اعتراض بالکل
غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ معاہدہ کے وہ الفاظ جو صیح ترین روایت میں بیان ہوئے ہیں ان میں صراحتاً
مذکور ہے کہ معاہدہ میں صرف مرد مراد تھے نہ کہ مرد اور عورتیں دونوں.چنانچہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں
صحیح بخاری میں معاہدہ کے یہ الفاظ درج ہیں :
ما
لا يَاتِيكَ مِنَّارَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا
یعنی ”ہم میں سے جو مرد بھی آپ کی طرف جائے گا وہ خواہ مسلمان ہی ہوگا اسے ہماری
طرف لوٹا دیا جائے گا.“
بخاری کتاب الشروط
Page 891
ALY
ان واضح اور غیر مشکوک الفاظ کے ہوتے ہوئے یہ اعتراض کرنا کہ دراصل معاہدہ میں مرد وعورت
دونوں مراد تھے صرف بے انصافی ہی نہیں بلکہ انتہائی بددیانتی ہے.اور اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ کی بعض
روایتوں میں معاہدہ کے الفاظ میں رجل ( مرد ) کا لفظ مذکور نہیں بلکہ عام الفاظ استعمال کئے گئے ہیں
جن میں مرد و عورت دونوں شامل سمجھے جاسکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو بہر حال مضبوط روایت کو
مقدم سمجھا جائے گا اور جب صحیح ترین روایت میں رجل ( مرد ) کا لفظ آتا ہے تو لازماً اس کو صحیح لفظ قرار دینا
ہوگا علاوہ ازیں جو الفاظ تاریخی روایت میں آتے ہیں وہ بھی اگر غور کیا جائے تو اسی تشریح کے حامل ہیں جو
ہم نے اوپر بیان کی ہے.مثلاً تاریخ کی سب سے زیادہ مشہور اور معروف کتاب سیرۃ ابن ہشام میں یہ
الفاظ آتے ہیں:
مَنْ أَتَى مُحَمَّدًا مِنْ قُرَيْشٍ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيْهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ
یعنی ” جو شخص قریش میں سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس اپنے گارڈین کی اجازت
کے بغیر پہنچے گا اسے قریش کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا.“
عربی کے ان الفاظ میں بے شک ”مرد“ کا لفظ صراحتا بیان نہیں ہوا مگر عربی زبان کا ابتدائی علم رکھنے
والا شخص بھی جانتا ہے کہ عربی میں بخلاف بعض دوسری زبانوں کے عورت اور مرد کے لئے علیحدہ علیحدہ صیغے
اور علیحدہ علیحدہ ضمیر میں استعمال ہوتی ہیں اور اوپر کی عبارت میں شروع سے لے کر آخر تک مردوں والے
صیغے اور مردوں والی ضمیر میں استعمال کی گئی ہیں.پس جیسا کہ معاہدوں کی زبانوں کی تشریح کا اصول ہے
لازماً اس عبارت میں صرف مرد ہی شامل سمجھے جائیں گے نہ کہ عورت اور مرد دونوں.بیشک بعض اوقات
عام محاورہ میں مردانہ صیغہ بول کر اس سے مرد و عورت دونوں مراد لے لئے جاتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ
زیر بحث عبارت اس قسم کی عبارت نہیں ہے بلکہ معاہدہ کی عبارت ہے جسے قانون کا درجہ بلکہ اس سے بھی
اوپر کا درجہ حاصل ہوتا ہے.کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر رکھا جاتا ہے اور الفاظ کا انتخاب دونوں
فریقوں کی جرح اور منظوری کے بعد ہوتا ہے لہذا ایسی عبارت میں لازما و ہی معنی لئے جائیں گے جومحدود
ترین اور مخصوص ترین پہلور رکھتے ہوں.پس اس جہت سے بھی بہر حال یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس معاہدہ میں
صرف مرد شامل تھے نہ کہ مرد اور عورت دونوں.علاوہ ازیں جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے عورت جو ایک کمزور جنس ہے اور عموماً اپنے خاوند یا مرد رشتہ داروں
ل : سیرۃ ابن ہشام ذکر صلح حدیبیہ
Page 892
ALL
کے رحم پر ہوتی ہے اسے واپس لوٹانے کے یہ معنی تھے کہ اسے اسلام لانے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے کفر
اور شرک کی طرف لوٹا دیا جائے جو نہ صرف رحم و شفقت بلکہ عدل وانصاف کے جذ بہ سے بھی بعید تھا.بیشک ایک مرد کو واپس لوٹانے میں بھی اس کے لئے یہ خطرہ تھا کہ مکہ کے کفار سے مختلف قسم کے عذابوں اور
دکھوں میں مبتلا کریں گے مگر مرد پھر بھی مرد ہے.وہ نہ صرف تکلیفوں کا زیادہ مقابلہ کرسکتا ہے بلکہ حسب
ضرورت ادھر ادھر چھپ کر یا بھاگ کر یا جتھہ وغیرہ بنا کر اپنے لئے بچاؤ کے کئی رستے کھول سکتا ہے مگر ایک
بے بس عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس کے لئے ایسے حالات میں یا تو اسلام سے جبری محرومی کی صورت تھی اور
یا موت.اندریں حالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحیم و کریم ہستی سے بالکل بعید تھا کہ بے کس اور
بے بس مسلمان عورتوں کو ظالم کفار کے مظالم کی طرف لوٹا دیتے.پس جو کچھ کیا گیا وہ نہ صرف معاہدہ
کے الفاظ کی رو سے بالکل صحیح اور درست تھا بلکہ عدل وانصاف اور رحم و شفقت کے مسلّمہ اصول کے
لحاظ سے بھی عین مناسب اور درست تھا اور اعتراض کرنے والوں کے حصہ میں اس قابل افسوس شرم کے
سوا کچھ نہیں آیا کہ انہوں نے مظلوم اور بے بس عورتوں کی حفاظت کے انتظام پر بھی زبان طعن دراز
کرنے سے دریغ نہیں کیا.دوسرا اعتراض ابوبصیر کے واقعہ سے تعلق رکھتا ہے.مگر غور کرنے سے یہ اعتراض بھی بالکل بودا اور
کمزور ثابت ہوتا ہے.بیشک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا تھا کہ کفار مکہ میں سے جو شخص
یعنی جو مرد مدینہ بھاگ کر آجائے گا تو وہ خواہ مسلمان ہی ہوگا اسے مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی اور
واپس لوٹا دیا جائے گا مگر سوال یہ ہے کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی ؟
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں.بلکہ آپ نے اس معاہدہ کے ایفاء کا ایسا کامل اور شان دار نمونہ دکھایا کہ دنیا اس کی
نظیر لانے سے عاجز ہے.غور کرو اور دیکھو کہ ابو بصیر اسلام کی صداقت کا قائل ہوکر مکہ سے بھاگتا ہے
اور کفار کے مظالم سے محفوظ ہونے اور اپنا ایمان بچانے کے لئے چھپتا چھپا تا مدینہ میں پہنچ جاتا ہے مگر
اس کے ظالم رشتہ دار بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچتے ہیں اور اسے تلوار کے زور سے اسلام کی صداقت
سے منحرف کرنے کے لئے جبر اواپس لے جانا چاہتے ہیں.اس پر یہ دونوں فریق آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.ابو بصیر بھرائی ہوئی آواز اور سہمے ہوئے انداز میں عرض کرتا ہے کہ
یارسول اللہ! مجھے خدا نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور مکہ واپس جانے میں جو دکھ اور خطرہ کی زندگی
میرے سامنے ہے اسے آپ جانتے ہیں.خدا کے لئے مجھے واپس نہ لوٹائیں.مگر اس کے مقابل پر ابوبصیر
Page 893
ALA
کے رشتہ دار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہے کہ ہمارا جو آدمی
بھی مدینہ آئے گا اسے واپس لوٹا دیا جائے گا.ابو بصیر کا دکھ اور اپنے صحابہ کی غیرت آپ کی آنکھوں کے
سامنے ہے اور خود آپ کے اپنے جذبات آپ کے دل میں تلاطم برپا کر رہے ہیں مگر یہ امانت و دیانت کا
مجسمہ اپنے عہد پر چٹان کی طرح قائم رہتے ہوئے فرماتا ہے اور کن پیارے الفاظ میں فرماتا ہے:
يَا أَبَابَصِيرِ إِنَّاقَدْ اَعْطَيْنَا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ مَا قَدْ عَلِمْتَ وَلَا يَصْلَحُ لَنَا فِي دِينِنَا الْعَدْرَوَانَّ اللَّهَ
جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَّعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ خَرَجًا وَّ مَخْرَجًا فَانْطَلِقُ إِلَى قَوْمِكَ
یعنی ”اے ابو بصیر ! تم جانتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو اپنا عہد و پیمان دے چکے ہیں اور
ہمارے مذہب میں عہد شکنی جائز نہیں ہے.پس تم ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ.پھر اگر تم
صبر و استقلال کے ساتھ اسلام پر قائم رہو گے تو خدا تمہارے لئے اور تم جیسے دوسرے بے بس
مسلمانوں کے لئے خود کوئی نجات کا رستہ کھول دے گا.“
اس ارشاد نبوی پرابو بصیر مکہ والوں کے ساتھ واپس چلا گیا اور جب وہ مکہ کے رستہ میں اپنے قید
کرنے والوں کے ساتھ لڑائی میں غالب ہو کر پھر دوبارہ واپس آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے دیکھتے ہی غصہ کے ساتھ فرمایا:
وَيْلُ أُمِّهِ مُسْعِرُ حَرُبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ
یعنی خرابی ہو اس کی ماں کے لئے.یہ شخص تو لڑائی کی آگ بھڑکا رہا ہے.کاش اسے
کوئی سنبھالنے والا ہو.“
یہ الفاظ سنتے ہی ابو بصیر یہ یقین کر لیتا ہے کہ آپ اسے بہر حال واپس لوٹا دیں گے اور مدینہ سے
چپکے چپکے نکل آتا ہے اور ایک دور کی علیحدہ جگہ میں اپنا ٹھکانا بنالیتا ہے.اب اس سارے واقعہ کو انصاف
کی نظر سے دیکھو کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور آپ کے خلاف کیا
اعتراض ہوسکتا ہے؟ بلکہ حق یہ ہے کہ آپ نے اس معاملہ میں اپنے جذبات کو کچلتے ہوئے معاہدہ کو پورا کیا
اور نہ صرف ایک دفعہ بلکہ دو دفعہ ابو بصیر کو واپس لوٹا دیا اور واپس بھی ایسے شان دار الفاظ میں لوٹایا
کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی.آپ نے اپنے جذبات کو کچلا.اپنے صحابہ کے جذبات کو کچلا
اور ابو بصیر کے جذبات کو کچلا اور ہر حال میں معاہدہ کو پورا کیا.پھر اگر ابو بصیر خود اہل مکہ سے آزاد ہوکر
۲، ۳: بخاری کتاب الشروط
لے سیرۃ ابن ہشام
Page 894
129
کسی اور جگہ چلا گیا تو اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے اور معاہدہ کی وہ
کون سی شرط ہے جس کے مطابق آپ اس بات کے پابند تھے کہ خواہ ملکہ سے بھا گا ہوا شخص کہیں بھی ہو
آپ اسے مکہ میں واپس پہنچا دینے کے ذمہ دار ہوں گے.افسوس ! افسوس !! اسلام کے دشمنوں نے کسی
بات میں بھی اسلام سے انصاف نہیں کیا.اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر کو اس کے قائم کردہ کیمپ میں حکم
بھجوا سکتے تھے کہ تم مدینہ واپس چلے آؤ اور یہ کہ چونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا اس لئے آپ نے گویا معاہدہ کے
الفاظ کو تو نہیں مگر ان کی روح کو توڑا.سو یہ اعتراض بھی ایک سراسر جہالت کا اعتراض ہے اور خود معاہدہ
کے الفاظ اور ان الفاظ کی روح اسے رد کرتے ہیں.معاہدہ کی یہ شرط کہ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا مسلمان
بھاگ کر مدینہ میں پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس لوٹا دیں گے صاف طور پر ثابت کرتی ہے
کہ اس شرط کی غرض و غایت یہ تھی کہ ایسے شخص کو باوجود اس کے مسلمان ہونے کے مدینہ کی اسلامی سیاست
کے دائرہ میں قبول نہیں کیا جائے گا یعنی گو وہ عقیدہ کی رو سے مسلمان ہو گا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اسے اپنی مدنی سیاست میں شریک نہیں کریں گے.تو جب ایسا شخص خود معاہدہ کی شرائط کے ماتحت مدینہ کی
اسلامی سیاست سے خارج قرار دیا گیا تھا تو اس کے متعلق یہ مطالبہ کس طرح ہوسکتا تھا کہ وہ جہاں بھی ہو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دے کر واپس لوٹا دیں گے.پس یہ کتنا بھاری ظلم ہے کہ اگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو مدینہ میں رکھتے ہیں تو آپ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کا معاہدہ تھا کہ
مسلمان ہونے کے باوجود آپ اسے اپنی سیاست میں شامل نہیں کریں گے اور اگر آپ اسے اپنی مدنی
سیاست سے خارج کر کے اہل مکہ کے سپرد کرتے اور مدینہ سے نکالتے ہیں تو پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ
آپ اسے اپنی سیاست میں شامل کر کے حکم کیوں نہیں بھجواتے.پس سیاسی لحاظ سے یہ ایک ایسا بودا اور ایسا
کمزور اور ایسا لا یعنی اعتراض ہے کہ کوئی سمجھ دار شخص اس کی طرف توجہ نہیں کرسکتا اور حق یہ ہے کہ یہ
نامعقول شرط جو کفار کی طرف سے معاہدہ میں شامل کی گئی تھی کہ کسی مسلمان مہاجر کو مدینہ میں پناہ نہ دی
جائے خدا نے اسی کو ان کے لئے عذاب بنا کر بتا دیا کہ ہمارے رسول نے تو بہر حال معاہدہ کی پابندی کی
مگر تم نے اپنے رستہ میں خود کانٹے ہوئے اور خود اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیار سے اپنے ہاتھ کاٹے.جب تم نے خود کہا کہ ملکہ کا جو نو جوان بھی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں نہیں رکھیں گے اور یہ کہ وہ مدینہ کی سیاست سے خارج سمجھا جائے گا تو پھر اسی منہ سے تم یہ
Page 895
۸۸۰
مطالبہ کس طرح کر سکتے ہو کہ یہ مدنی سیاست سے خارج لوگ جہاں جہاں بھی ہوں انہیں آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم حکم دے کر اور ان پر اپنی سیاست قائم کر کے مکہ پہنچائیں ؟ تم نے خود یہ شرط پیش کی کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی روحوں پر اور ان کے امور اُخروی پر تو بیشک حکومت کریں مگران
کی سیاست اور دنیوی امور پر حاکم نہ بنیں اور جب تم نے خود انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیاست سے نکال دیا تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیسا؟ بہر حال یہ قریش مکہ کا اپنا مکر تھا
جو خود انہی پر لوٹ کر گرا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بہر صورت پاک تھا اور پاک رہا.آپ نے
معاہدہ کے الفاظ کو بھی پورا کیا اور ابو بصیر کو مکہ والوں کے سپرد کرتے ہوئے مدینہ سے رخصت کر دیا
اور پھر آپ نے معاہدہ کی روح کو بھی پورا کیا کہ جیسا کہ اس شرط کا اصل منشا تھا.آپ نے ابو بصیر اور اس
کے ساتھیوں کو اپنی سیاست کے دائرہ سے خارج رکھا.پس آپ ہر جہت سے بچے رہے اور کفار مکہ اپنے
ہی پھیلائے ہوئے جال کا خود شکار ہو کر رہ گئے اور بالآخر خود ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے کہ ہم اس
شرط کو معاہدہ سے خارج کرتے ہیں.اور یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہ کر کہ وَيْلُ أُمِّهِ مُسْعِرُ حَرُبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ
(یعنی اس کی ماں کے لئے خرابی ہو یہ شخص تو جنگ کی آگ بھڑ کار رہا ہے.کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہو )
ابوبصیر کو اشارہ کیا تھا کہ تم الگ پارٹی بنا کر قریش سے جنگ شروع کردو، کتنا ظلم اور کتنی گندی ذہنیت اور
حالات پیش آمدہ سے کتنی جہالت ہے ! یہ الفاظ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نا واجب جنگ
سے آپ کی بیزاری کا بین ثبوت ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ ابوبصیر کے اس فعل سے
بریت اور بیزاری کا اظہار فرمارہے ہیں نہ یہ کہ اسے کوئی مخفی اشارہ دے کر جنگ پر ابھارنا چاہتے ہیں.اور اگر کوئی شخص یہ خیال کرے جیسا کہ سرولیم میور نے خیال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
آخری الفاظ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر اسے کوئی ساتھی مل جائے اور اس سے
پتہ لگتا ہے کہ آپ کا یہی منشا تھا کہ اگر ابو بصیر کو کوئی ساتھی مل جائے تو وہ جنگ کی آگ بھڑکا سکتا ہے اور
اس طرح اس کلام میں گویا جنگ کی انگیخت کا اشارہ پایا جاتا ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ اول تو جو معنی ہم
نے کئے ہیں وہ عربی محاورہ کے عین مطابق ہیں جس کی مثالیں حدیث میں بھی کثرت سے ملتی ہیں.علاوہ
ازیں اگر بالفرض دوسرے معنی جائز بھی ہوں تو پھر بھی عبارت کے سیاق وسباق کے ماتحت اس فقرہ کا
مطلب اس کے سوا کوئی اور نہیں لیا جا سکتا کہ اگر ابو بصیر کو اس کا کوئی ہم خیال ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی
Page 896
ΑΛΙ
آگ بھڑ کا دے مگر شکر ہے کہ اسے مدینہ میں کوئی ایسا ساتھی میسر نہیں.پس خواہ کوئی معنی لئے جائیں
اس عبارت کا سیاق و سباق اور اس کے ابتدائی ٹکڑے اس بات کا کافی وشافی ثبوت ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ابو بصیر کو ملامت کرنا تھا نہ کہ جنگ کے لئے اُبھارنا.کیا اپنے کلام کو اس غصہ اور
ملامت کے الفاظ سے شروع کرنے والا شخص کہ فلاں شخص کی ماں کے لئے خرابی ہو وہ تو جنگ کی آگ
بھڑ کانے والا ہے.اس کے معا بعد اس قسم کے الفاظ منہ پر لا سکتا ہے کہ ہاں ہاں جنگ کی آگ بھڑ کا ؤ ؟
آخر اعتراض کرنے کے شوق میں عقل کو تو ہاتھ سے نہیں دینا چاہئے ! پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھنے والی
ہے کہ خود ابو بصیر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے کیا اثر کیا اور اس نے آپ کا کیا مطلب
سمجھا.سو اس کے متعلق اسی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ :
فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ
یعنی ” جب ابو بصیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو اس نے سمجھ لیا کہ
آپ بہر حال اسے مکہ والوں کی طرف واپس لوٹا دیں گے.جس پر وہ چپکے سے بھاگ کر
دوسری طرف نکل گیا.افسوس ! صد افسوس ! کہ جس شخص کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے گئے وہ خود تو ان کا یہ مطلب سمجھا کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس فعل کو نا پسند کیا ہے اور آپ بہر حال اسے مکہ کی طرف واپس
لوٹا دیں گے مگر ہمارے تیرہ سو سال بعد آنے والے مہربان یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل آپ نے ابو بصیر کو
الگ پارٹی بنا کر جنگ کرنے کی انگیخت کی تھی.تعصب کا ستیاناس ہو.بے انصافی کی بھی کوئی حد ہونی چاہئے.اسلامی سیاست اسلام کے دینی ابوبصیر والے واقعہ سے اسلامی اصول سیاست کے متعلق بھی
ایک اہم استدلال ہوتا ہے یعنی یہ کہ خاص حالات میں بعض
نظام سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے علاقوں کے مسلمانوں کی سیاست ان کے مشترکہ دینی نظام.علیحدہ بھی ہو سکتی ہے.میرا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو اپنے ایسے سیاسی نظام میں جو خود ان کے اپنے
اختیار میں ہو اسلامی اصولوں کے ترک کر دینے کا اختیار ہے.کیونکہ بہر حال جو قوم بھی اسلام پر ایمان لاتی
ہے اس کا فرض ہے کہ اپنی دینی اور دنیوی زندگی کو اسلام کی تعلیم کے مطابق بنائے.پس میری مراد یہ نہیں
کہ مسلمانوں کا کوئی حصہ اپنی سیاست میں دینی اصولوں کو ترک کر دینے کا حق رکھتا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ
بخاری کتاب الشروط
Page 897
۸۸۲
اگر مسلمان دو یا دو سے زیادہ علیحدہ علیحدہ ملکوں میں آباد ہوں یا جغرافیائی لحاظ سے ایک ملک میں رہتے
ہوئے بھی ان کی تنظیم ایک دوسرے سے جدا گانہ ہوتو وہ ایک مشتر کہ امام اور مقتدا کی دینی اور روحانی
قیادت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی اپنی علیحدہ علیحدہ سیاست قائم کر سکتے ہیں بلکہ اگر اس صورت میں ایک
پارٹی امام کی روحانی اقتدا کے علاوہ امام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی سیاست میں منسلک ہو تو پھر بھی
دوسری پارٹی امام کی دینی اور روحانی اقتدا میں ہونے کی باوجود اپنا علیحدہ سیاسی نظام رکھ سکتی ہے گویا اس
صورت میں جہاں ایک پارٹی دینی اور سیاسی ہر دو لحاظ سے امام کے ساتھ ہوگی وہاں دوسری پارٹی دینی لحاظ
سے تو امام کے ساتھ ہوگی مگر سیاست میں علیحدہ نظام رکھے گی.یہ استدلال ابوبصیر کے واقعہ سے اس طرح
ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی اس شرط کو قبول کیا کہ اگر مکہ کا کوئی مسلمان مدینہ میں
آئے تو آپ اسے مدینہ میں رکھ کر اپنی سیاست میں شامل نہیں کریں گے بلکہ واپس لوٹا دیں گے اور پھر
اس شرط کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی ابو بصیر اور اس کی پارٹی کو ان کے مسلمان ہونے
کے باوجود مدینہ کی سیاست سے خارج رکھا.پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کی اس شرط کو قبول کرنا اور
اس کے مطابق عمل کرنا ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اس طریق کو جائز قرار دیا ہے کہ مختلف علاقوں کے
مسلمان ایک دین پر قائم ہوتے ہوئے بلکہ ایک امام کے ماتحت ہوتے ہوئے بھی اپنی علیحدہ علیحدہ سیاست
رکھ سکتے ہیں اور یہ ایک نہایت اہم استدلال ہے جو ابو بصیر کے واقعہ کے تعلق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے
عمل سے ہوتا ہے اور دراصل اسی قسم کے حالات کے پیش نظر قرآن شریف کی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ:
وَاِنْ طَابِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ
احْدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ
فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ :
یعنی اگر مومنوں میں سے دو پارٹیاں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو پھر اگر
صلح کے بعد ان میں سے کوئی پارٹی دوسری کے خلاف سینہ زوری اور سرکشی سے کام لے (اور
شرائط کو توڑے تو پھر سب مل کر اس پارٹی کے خلاف لڑائی کرو جو سرکشی سے کام لے رہی ہو
یہاں تک کہ وہ سیدھی ہو کر خدا کے فیصلہ کے سامنے جھک جائے.پھر اگر وہ سینہ زوری اور سرکشی
سے باز آ کر جھک جائے تو پھر ان دونوں پارٹیوں کے درمیان پورے عدل وانصاف کے ساتھ
ل: سورة الحجرات : ١٠
Page 898
۸۸۳
صلح کرا دو اور دیکھو عدل کے ترازو کو بہر حال برابر رکھو.کیونکہ خدا عدل کرنے والے لوگوں کو
پسند کرتا ہے.“
اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں افراد کی لڑائی یا ایک سیاسی نظام کے اندر رہنے والی پارٹیوں
کی باہم لڑائی مراد نہیں ہے بلکہ ایسی پارٹیوں کی لڑائی مراد ہے جو اسلام پر قائم ہونے اور دینی لحاظ سے
متحد ہونے کے باوجود علیحدہ علیحدہ سیاسی نظام رکھتی ہیں.بلکہ یہ وہ زریں اصول ہے جو صرف اسلامی
پارٹیوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں اور تمام پارٹیوں پر یکساں چسپاں ہوتا ہے اور
دراصل یہی وہ اصول ہے جو برسر پر کا رقوموں کے درمیان حقیقی امن قائم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے.
Page 899
۸۸۴
اسلام کی امن اور جنگ کی طاقت کا مقابلہ
صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے ہے
جس کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے.اس نئے دور کا آغاز غزوہ
احزاب سے ہوا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا یعنی
آئندہ قریش مکہ پر ہم چڑھائی کریں گے مگر انہیں مدینہ کے خلاف چڑھائی کرنے کی ہمت نہیں
ہوگی.اس نئے دور کی تکمیل صلح حدیبیہ سے ہوئی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان
ایک با قاعدہ معاہدہ کے ذریعہ لڑائی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور انیس سال کی طویل کشمکش کے بعد جو شروع میں
جابرانہ تشد داور تعذیب کا رنگ رکھتی تھی اور آخر میں با قاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر گئی.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لئے کم از کم جہاں تک اہل مکہ کا تعلق تھا امن کا ماحول قائم ہو گیا.سواس موقع
پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اسلام کی اس انیس سالہ خون آلود زندگی پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ ان
انیس سالوں میں اسلام نے کس رنگ میں ترقی کی اور اس کے بعد امن کے دور میں (امن سے مراد نسبتی امن
ہے کیونکہ گومکہ کے ساتھ صلح ہوگئی تھی مگر عرب کی دوسری قو میں ابھی تک اسلام کے خلاف برسر پیکار تھیں )
اسلام کی ترقی نے کیا صورت اختیار کی ؟ یہ ایک نہایت لطیف مقابلہ ہو گا جس سے ہر انصاف پسند محقق اور
مبصر کو اسلام کی امن اور جنگ کی طاقت کے موازنہ کا بہت اچھا معیار حاصل ہو سکے گا.یہ ظاہر ہے کہ اسلام کی ابتدائی مردم شماری کا ریکارڈ موجود نہیں ہے اس لئے ہمیں لازماً اسلام کی ترقی
کی رفتار کا اندازہ اس تعداد سے لگانا ہوگا جو ابتدائی اسلامی لڑائیوں میں شریک ہوتی رہی ہے اور نسبتی ترقی
کو دیکھنے کے لئے یہ طریق کافی تسلی بخش ہے.سو چھوٹے چھوٹے درمیانی واقعات کو چھوڑتے ہوئے ہم
دیکھتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی میں یعنی جنگ بدر کے موقع پر جو۲ ہجری میں ہوئی مسلمان
مجاہدین کی تعداد باختلاف روایت تین سو دس سے لے کر تین سو انیس تک تھی..اس کے بعد اُحد کی لڑائی
بخاری بحوالہ زرقانی
بخاری وزرقانی
Page 900
۸۸۵
ہجری میں ہوئی اور اس میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعداد سات سو تھی یا اُحد کے بعد بڑی
لڑائی غزوہ خندق تھی جو ۵ ہجری میں ہوئی.اس لڑائی میں گوخندق وغیرہ کے کھود نے کے کام پر بچے اور
بوڑھے سب مسلمان ملا کر کل تعداد تین ہزار ہو گئی تھی.کیونکہ یہ لڑائی ہوئی بھی گویا مدینہ کے اندر تھی اور
گھر سے باہر نکلنے کا سوال نہیں تھا مگر غالباً عملا لڑائی کے وقت صرف ایک ہزار مسلمان شریک ہوئے تھے.کے
اس کے بعد ۶ ہجری میں صلح حدیبیہ کا غزوہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سو بیان ہوئی ہے ہے
یہ کل انیس سال ہوئے کیونکہ قریباً تیرہ سال کی زندگی والے اور قریباً چھ سال صلح حدیبیہ تک کی مدنی زندگی
والے ملا کر کل انیس سال بنتے ہیں.گویا ان انیس سالوں میں جو ابتداء مکہ کے جابرانہ تشدد اور بعد میں
با قاعدہ لڑائی کی حالت میں گزرے اسلام کل چودہ سو مسلمان جوان پیدا کر سکا.اس کے بعد امن اور صلح کا
زمانہ آتا ہے.اس میں مسلمانوں کی تعداد نے جو ترقی کی اس کا اندازہ اس تعداد سے ہوسکتا ہے جو صلح
حدیبیہ کے دوسال بعد یعنی ۸ ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر شریک ہوئی.یہ تعداد مسلمہ طور پر دس ہزار تھی.گویا جہاں جنگ کے زمانہ میں انیس سال کی طویل جد و جہد نے صرف چودہ سو مسلمان پیدا کئے وہاں اس
کے بعد امن کے زمانہ میں دو سال کی پر امن تبلیغ نے اس تعداد میں آٹھ ہزار چھ سو کا اضافہ کر دیا.یہ
حیرت انگیز فرق اس طرح پیدا ہوا کہ ایک طرف تو جنگ کے زمانہ میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان
باہم میل ملاقات کا بہت کم موقع ملتا تھا اس لئے اسی نسبت سے کفار کو اسلام کی دلکش تعلیم کے سننے اور اس
سے متاثر ہونے کا موقع بھی بہت کم میسر آتا تھا اور دوسری طرف جولوگ جنگ کے زمانہ میں اسلام کی تعلیم
سے متاثر ہوتے تھے ان میں سے بھی اکثر اس زمانہ کی غیر معمولی تکالیف اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے
آگے آنے سے ڈرتے تھے لیکن جب جنگ ختم ہونے سے صلح کا ماحول قائم ہوا تو گویا وہ بھاری
بند جو اسلام کے دریا کے بہاؤ کو روکے ہوئے تھا یکلخت ٹوٹ کر گر گیا اور اسلام کے حیات افزا پانیوں کو
کھلا رستہ ملنے سے اسلام نے وہ حیرت انگیز ترقی کی جو ہمارے سامنے ہے.کیا اس واضح نظارے کو
دیکھتے ہوئے کوئی منصف مزاج انسان یہ اعتراض منہ پر لاسکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟
دیکھو اور غور کرو کہ جب تلوار نیام سے باہر تھی تو انیس سال کی طویل جد و جہد نے صرف چودہ سو مسلمان
پیدا کئے لیکن جب یہ تلوار نیام کے اندر آگئی تو دو سال کے قلیل عرصہ نے ساڑھے آٹھ ہزار انسانوں کو
ے ابن اسحاق بحوالہ زرقانی
: تاریخ خمیس
: ابن سعد وابن اسحاق
۴، ۵ : بخاری
Page 901
ΑΛΥ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا.یہ وہ ٹھوس اور بولتے ہوئے اعدادوشمار ہیں جن پر کسی
متعصب سے متعصب انسان کا تعصب بھی پردہ نہیں ڈال سکتا.آؤ اب ذرا ان اعداد و شمار کی مزید تفصیل میں جا کر پورا حساب نکالیں کہ اسلام کی امن کی طاقت کو
اس کی جنگ کی طاقت کے مقابلہ پر کیا وزن حاصل ہے.موٹے طور پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنگ کے
انیس سالوں نے چودہ سو مسلمان پیدا کئے اور اس کے مقابل پر امن کے دو سالوں نے اس تعداد میں
آٹھ ہزار چھ سو مسلمانوں کا اضافہ کیا لیکن اگر زیادہ حسابی نظر سے دیکھا جائے تو جو زمانہ ہم نے انیس سال
کا شمار کیا ہے وہ دراصل کسروں میں جا کر اٹھارہ اور انیس سال کے درمیان یعنی قریباً ساڑھے اٹھارہ سال
بنتا ہے اسی طرح ہم نے صلح حدیبیہ کے وقت جو تعداد چودہ سو شمار کی ہے اس کے متعلق صحیح روایات سے پتہ
لگتا ہے کہ دراصل وہ چودہ سو اور پندرہ سو کے درمیان تھی یے یعنی اسے ساڑھے چودہ سو سمجھنا چاہئے مگر ا بھی
اس کے علاوہ ایک اور فرق بھی ہے جو صحیح حسابی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے دور کرنا ضروری ہے.وہ فرق یہ ہے
کہ تاریخ و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوی نبوت کے ابتدائی تین سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بالکل خاموشی کے ساتھ انفرادی تبلیغ میں گزارے تھے اور اسلام کی تبلیغ کو عام نہیں کیا تھا.پس ان ابتدائی
تین سالوں کو ساڑھے اٹھارہ سال کے عرصہ میں سے منہا کرنا ضروری ہے.اس طرح جنگ کے زمانہ میں
اصل تبلیغی جد و جہد کا عرصہ ساڑھے پندرہ سال بنتا ہے.گویا نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ والے ساڑھے پندرہ سال
میں ساڑھے چودہ سو مرد مسلمان ہوئے اور اس کے مقابل پر امن و صلح والے دو سال میں اس تعداد پر آٹھ
ہزار پانچ سو پچاس کا اضافہ ہوا.اس طرح ان دونوں زمانوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ جنگ والے زمانہ کی رفتار
ترقی ۱۴۵۰ : ۱۵ یعنی ۲۹ فی سال بنی اور امن و صلح والے زمانہ کی رفتار ۸۵۵۰ فی سال نکلی اور اگلا
حساب ایک بچہ بھی نکال سکتا ہے جو یہ ہے کہ ان دونوں کی باہمی نسبت ایک کے مقابلہ پر چھیالیس بنتی
ہے.یعنی اگر جنگ کے زمانہ کی تبلیغی طاقت کا نتیجہ ایک ہو تو اس کے مقابل پر امن کے زمانہ کی تبلیغی طاقت
کا نتیجہ چھیالیس ہوگا اور یہ بعینہ وہی نسبت ہے جو ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مومن کے
مقابلہ پر ایک نبی اللہ کی قرار دی ہے.چنانچہ آپ فرماتے ہیں:
الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِّنْ سِنَةٍ وَّاَرْبَعِينَ جُزُاً مِّنَ النُّبُوَّةِ -
یعنی ” ایک مومن کی سچی رؤیا ایک نبی کی نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہوتی ہے.“
زرقانی بحوالہ بخاری
تاریخ خمیس
س بخاری کتاب التعبير
Page 902
۸۸۷
اب غور کرو کہ یہ کیسی عجیب و غریب اور کیسی لطیف مطابقت ہے کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اس
کے جنگ کے زمانہ کی طاقت اس کے امن کے زمانہ کی طاقت کے مقابلہ پر بعینہ وہی حیثیت رکھنے والی
ثابت ہوئی ہے جو ایک نبی اللہ کے مقابلہ میں عام مومن کی ہوا کرتی ہے اور یہ ایک بار یک روحانی نکتہ
ہے جس سے کئی اہم مسائل پر اصولی روشنی پڑتی ہے مثلاً :
-1
-٢
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی اصل روحانی طاقت امن کے زمانہ کی تبلیغ میں ہے نہ کہ جنگ
کی معرکہ آرائی میں اور عقلاً بھی یہی ہونا چاہئے کیونکہ وہ پر امن تبلیغ جس میں دلائل و براہین اور
آیات بینات کے ذریعہ اسلام کی خوبی اور برتری ثابت کی جائے یقیناً وہی اسلام کی اندرونی
قوت کی علمبر دار ہے اور اس کے مقابل پر جنگ کا ماحول ایک محض خارجی چیز ہے جو صرف منکرین
کی عداوت کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اصل اندرونی طاقت جو گویا اسلام کے ذاتی اور
مستقل جو ہر کا رنگ رکھتی ہے خارجی عنصر کے نتائج پر بہر حال غالب ہونی چاہئے.پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ خود اپنی روحانی طاقت
اور اندرونی جاذبیت اور دلائل کے غلبہ سے پھیلا ہے..اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ذاتی میلان امن وصلح
کی طرف تھا نہ کہ جنگ کی طرف اور جنگ کی حالت صرف منکرین کی پیدا کی ہوئی چیز تھی جس میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور داخل ہونا پڑا.یہ وہ تین زبر دست نتائج ہیں جنہیں قبول کرنے کے لئے ہر عقل مند اور منصف مزاج انسان مجبور
ہے اور ان کے ذریعہ اسلام کی ابتدائی تاریخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ وسوانح پر ایک ایسی
اصولی روشنی پڑتی ہے کہ اس سے یہ سارا میدان ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھتا ہے.بیشک جہاد
بالسیف بھی اسلامی تعلیم کا ایک ضروری حصہ ہے کیونکہ جو قوم یا حکومت اسلام کو بز ورمٹانے کے لئے تلوار
اٹھاتی ہے یا اسلام کی اشاعت کو تلوار کے زور سے روکنا چاہتی ہے اس کے مقابلہ کے لئے اسلام بھی
تلوار ہی اٹھانے کا حکم دیتا ہے.اور نہ صرف تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے بلکہ ہدایت فرماتا ہے کہ ایسے ظالم
دشمن کے خلاف اس طرح ڈٹ کر لڑو کہ گویا تم ایک سیسہ پلائی ہوئی آہنی دیوار ہو.اور اسے ایسی مار مارو
کہ صرف وہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے آنے والے دوسرے دشمن بھی لرزہ براندم ہو کر منتشر ہو جائیں.مگر
ل : سورة الحج : ۴۰ : ۴۰ و ۴۱
: سورة الصف : ۵
: سورۃ الانفال : ۵۸
Page 903
۸۸۸
ان ظالم دشمنوں کو چھوڑ کر جو اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے میں پہل کرتے اور اسلام کو جبر وطاقت کے
زور سے مٹانے کے درپے رہتے ہیں اسلام ساری قوموں کے لئے پر امن تبلیغ کا پیغام لے کر آیا ہے اور
اس کے اس پیغام میں اس کی روحانی طاقت کی شان اور اس کے خدا داد براہین کا غلب مخفی ہے اور یہی وہ جہاد
ہے جسے اسلام میں تلوار کے جہاد کے مقابل پر جہاد کبیر (یعنی بڑا جہاد ) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے.اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ صحابہ کی ایک پارٹی ایک غزوہ سے واپس لوٹی تو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ اب تم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہادا کبر کی طرف
آرہے ہو اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ! جہاد کبر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”انسان کا
اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا.ا : سورة الفرقان : ۵۳
بیہقی
Page 904
۸۸۹
اسود و احمر کے نام اسلام کا پیغام
قیصر و کسریٰ کو دعوت حق
ہم بتا چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے ساتھ اسلام کی تاریخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے.یہ نیا دور کامل امن کا دور تو ہر گز نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ ابھی تک عرب کے
بہت سے قبیلے اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے لیکن ہاں چونکہ عربوں میں قریش کا قبیلہ خانہ کعبہ کا متولی
ہونے کی وجہ سے عموماً سارے قبیلوں میں معزز سمجھا جاتا تھا اور اسلام کے خلاف جنگ کی ابتدا بھی اسی قبیلہ
کی طرف سے ہوئی تھی اس لئے قریش کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو جانے کے نتیجہ میں ملک کے ایک حصہ میں
عارضی امن کی صورت ضرور پیدا ہو گئی تھی اور اس جزوی امن کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
پہلا قدم اٹھایا وہ آپ کے خداداد منصب نبوت کے تبلیغی پہلو کا ایک نہایت شاندار کارنامہ تھا.ہماری مراد
ان تبلیغی مراسلات سے ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معابعد مختلف ملکوں کے
بادشاہوں اور رئیسوں کے نام ارسال فرمائے اور اس بات کا عملی ثبوت پیش کیا کہ آپ کی توجہ کا مرکزی
نقطہ تبلیغ اسلام ہے.یعنی اس ابدی اور آخری صداقت کا اقوام عالم تک پہنچا نا جو خداوند عالم نے آپ کے
ذریعہ دنیا میں نازل فرمائی مگران عالمگیر تبلیغی خطوط کے ذکر سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلام
کے تبلیغی مذہب ہونے کے متعلق ایک اصولی نوٹ درج کر کے ناظرین کو بتایا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا تبلیغی نظر یہ کیا تھا اور آپ کی بعثت کی غرض کتنے وسیع میدان پر پھیلی ہوئی تھی.اسلام کا تبلیغی نظریہ سو سب سے پہلے جانا چاہئے کہ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے اور اس کے مقدس
بانی کو حکم دیا گیا ہے کہ جو صداقت بھی اسلام کے ذریعہ آسمان سے نازل ہوئی ہے
اسے اپنے آپ تک چھپا کر نہ رکھے بلکہ لوگوں تک پہنچائے.اور اس کے سارے پہلوؤں کو کھول کھول کر
بیان کر دے.چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومخاطب کر کے فرماتا ہے:
Page 905
190
ياَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبَّكَ وَ إِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
یعنی اے خدا کے رسول جو کچھ بھی تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اُتارا گیا ہے وہ لوگوں
تک کھول کھول کر پہنچا دے اور اگر تو نے ایسا نہ کیا ( اور کسی حصہ کو چھپا کر رکھا اور کسی کو بیان
کر دیا ) تو جان لے کہ اس صورت میں تو خدا کی رسالت کو پہنچانے والا نہیں سمجھا جائے گا.“
اور یہ فریضہ تبلیغ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ آپ پر ایمان
لانے والوں کا بھی یہی فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اسلام کی صداقتوں کو دوسروں تک پہنچا ئیں چنانچہ
قرآن شریف فرماتا ہے:
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ
یعنی اے مسلمانو! تم دنیا کی بہترین امت بنا کر اقوام عالم کے فائدہ کے لئے قائم
کئے گئے ہو.تمہارا یہ کام ہے کہ لوگوں کو اسلام کی نیکی کی طرف بلا ؤ اور خلاف اسلام بدی
سے روکو.“
پھر اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک حصہ ہمیشہ تبلیغ اسلام کی خدمت
کے لئے وقف رہنا چاہئے جو گویا اپنے آپ کو کلیتاً خدمت دین کے لئے وقف کر دے چنانچہ فرماتا ہے:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ :
یعنی چاہئے کہ تم میں سے ملت کا ایک حصہ تبلیغ حق کے لئے وقف رہے اس کا کام لوگوں
کو نیکی کی طرف بلانا اور بھلائی کی تلقین کرنا اور بدی سے روکنا ہو اور بات یہ ہے کہ یہی لوگ
حقیقتاً با مراد ہیں.66
دین کے معاملہ میں جبر جائز نہیں فریضہ تبلیغ کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ ہی قرآن شریف
یہ اصول سکھاتا ہے کہ تبلیغ ہمیشہ نہایت احسن طریق پر
حکمت و دانائی کے رنگ میں ہونی چاہئے تا کہ صداقت پسند مخاطب کے دل میں ضد اور دوری پیدا ہونے کی
: سورۃ المائده : ۶۸
: سورة آل عمران :
11:
ے : سورة آل عمران : ۱۰۵
Page 906
۸۹۱
بجائے اس کے دل کی کھڑکیاں سچائی کے قبول کرنے کے لئے خود بخود کھلتی چلی جائیں.چنانچہ فرماتا ہے:
أدْعُ إلى سَبِيْلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
یعنی ” اے خدا کے رسول اپنے رب کے رستہ کی طرف حکمت اور عمدہ طریق نصیحت کے
رنگ میں لوگوں کو دعوت دو اور اگر کبھی بحث و مجادلہ کی صورت پیدا ہو جائے تو بحث بھی دلکش
اور بہترین انداز میں کرو.“
پھر اسی اصول کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دین کے معاملہ میں جبر وا کراہ کا طریق
کسی طرح جائز نہیں اور نہ جبر و تشدد کے نتیجہ میں سچا ایمان پیدا ہوسکتا ہے.پس دلائل و براہین کے ساتھ سمجھا
دینے کے بعد مخاطب کو یہ اختیار ہونا چاہئے کہ اگر وہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو انکار کر دے کیونکہ
آزادانہ اقرار یا انکار کے بغیر کوئی شخص انعام یا سزا کا مستحق نہیں سمجھا جا سکتا.چنانچہ فرماتا ہے:
-1
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَى
یعنی دین کے معاملہ میں جبر نہیں ہو سکتا.ہدایت اور گمراہی کھلی کھلی چیزیں ہیں اور ہر شخص خود
فیصلہ کا حق رکھتا ہے.اور دوسری جگہ فرماتا ہے:
-r
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا -
پس جو شخص چاہے ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے انکار کر دے.ہاں جولوگ انکار کر
کے ظالم بنیں گے ان کے لئے آخرت میں ضرور آگ کا عذاب مقدر ہے.“
پھر اسی لطیف مضمون کے دوسرے پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جبر کے نتیجہ میں پیدا
شدہ ایمان قطعاً کوئی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ حق یہ ہے کہ وہ ایمان کہلانے کا حق دار ہی نہیں کیونکہ اس صورت
میں انسان کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے.اور انعام کا مستحق ہونا تو درکنار ایسے
دور نے منافق دو ہرے عذاب کے سزاوار ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کفر کے جرم کے ساتھ جھوٹ اور
دھو کے بازی کے جرم کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں.وہ کافر ہیں کیونکہ ان کے دل میں کفر ہوتا ہے اور وہ جھوٹے
اور دھو کے باز ہیں کیونکہ وہ اپنے دل کے یقین کے خلاف مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے زبان سے
ا : سورة النحل : ۱۲۶ : سورة البقره : ۲۵۷
ل : سورة الكهف : ۳۰
Page 907
۸۹۲
جھوٹے طور پر اسلام کا اقرار کرتے ہیں.چنانچہ فرماتا ہے:
إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ
یعنی ” منافق لوگ جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کے دل میں کفر بھرا
ہوتا ہے وہ آخرت میں دوزخ کی آگ کی سب سے سخت اور سب سے نیچے کی تہہ میں رکھے
جائیں گے.“
اسلام کا عالمگیر مشن بالآخر اسلام اس سوال کو لیتا ہے کہ گزشتہ نبیوں ( یعنی حضرت موسیٰ، حضرت عیسی
اور کرشن علیہم السلام وغیرہ) کے خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن
صرف اپنی قوم یعنی عربوں تک ہی محدود نہیں ہے اور نہ صرف کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ
دنیا کی ساری قوموں کے لئے ہے اور سارے زمانوں سے تعلق رکھتا ہے.اس لئے مسلمانوں کو ساری
قوموں کی طرف یکساں توجہ دینی چاہئے.چنانچہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے:
قُلْ يَايُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۚ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوتِ
وَالْأَرْضِ
یعنی اے نبی تو لوگوں سے کہہ دے کہ خدا نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا
ہے.ہاں وہی خدا جو اس کل کائنات یعنی آسمانوں اور زمین کا مالک و آقا ہے.“
اور اس ہدایت کی تشریح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عالمگیر مشن کے متعلق فرماتے ہیں :
أعْطِيتُ خَمْسَالَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِى نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ
شَهرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطُهُوراً وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَأُعْطِيتُ
الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثَ إِلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَّبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً - وَفِي
رِوَايَةٍ بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ
یعنی مجھے پانچ ایسی باتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں.(۱) مجھے ایک ماہ کی مسافت تک خدا داد رعب عطا کیا گیا ہے (۲) میرے لئے تمام زمین مسجد
اور طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے (۳) میرے لئے جنگوں میں حاصل شدہ مال غنیمت جائز قرار
: سورۃ النساء : ۱۴۶
سورۃ الاعراف : ۱۵۹
بخاری کتاب
التیم
: مسند احمد جلد ۲
Page 908
۸۹۳
دیا گیا ہے (۴) مجھے شفاعت کا مقام عطا کیا گیا ہے اور (۵) مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی خاص قوم
کی طرف مبعوث ہوتا تھا مگر مجھے سب بنی نوع آدم کے لئے مبعوث کیا گیا ہے اور (ایک
روایت میں یہ ہے کہ ) میں اسود واحمر کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانچوں خصوصیات اپنے اندر نہایت شاندار پہلو رکھتی ہیں مگر اس جگہ
ہمارا تعلق صرف پانچویں خصوصیت کے ساتھ ہے جس میں نہایت واضح الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کا پیغام دنیا کی ساری قوموں کے واسطے ہے نہ کہ صرف کسی
ایک قوم کے واسطے.اسلام کی دائمی شریعت پھر قرآنی شریعت کے دائگی اور ناقابل تنسیخ ہونے کے متعلق خدا تعالیٰ
فرماتا ہے:
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ
لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
یعنی اے لوگو میں نے آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمتوں کے
دروازے کھول دئے اور میں نے تمہارے واسطے اسلام کا دین پسند کیا ہے.“
روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ بعض یہودیوں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ آپ لوگوں پر ایک ایسی آیت
(یعنی یہی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...والی آیت اتری ہے کہ اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس
دن کو اپنے واسطے عید بنالیتے.حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہمارے لئے تو خدا نے اسے عید بنارکھا ہے
کیونکہ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے مقدس موقع پر اور عرفہ کے متبرک مقام میں نازل ہوئی
تھی جبکہ اس کے بعد کا دن عیدالاضحی کا دن تھا اور مجھے یہ ساری تفصیل یاد ہے.پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث میں فرماتے ہیں کہ :
إِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِى هَذَا اخِرُ الْمَسَاجِدِ - E
یعنی ” میں آخری نبی ہوں (میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو میرے دور نبوت کو
منسوخ کر دے) اور میری یہ مسجد آخری مسجد ہے ( جس کے بعد کوئی ایسی عبادت گاہ نہیں
ہو سکتی جو میری مسجد کو منسوخ کر کے نیا طریق عبادت جاری کر دے.)
: سورة المائده : ۴ بخاری کتاب التفسير سورة المائدة
سے صحیح مسلم
Page 909
۸۹۴
یا درکھنا چاہئے کہ الفاظ ” میری یہ مسجد آخری مسجد ہے“ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میری اس مسجد کے بعد
کوئی مسجد نہیں بنے گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء
نے بہت سے مسجدیں بنائیں اور آج تک اسلامی ممالک میں لاکھوں کروڑوں مسجدیں بنتی چلی آئی
ہیں.پس مراد یہ ہے کہ آئندہ میری مسجد کے مقابل پر کوئی مسجد نہیں بنے گی بلکہ جو سچی مسجد بھی ہوگی وہ
لا ز ما میری مسجد کی نقل اور ظل ہوگی.اور اسی حقیقت کو ایک اور لطیف رنگ میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ :
أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ
یعنی ”میں اور قیامت اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ جس طرح
میری یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں (اور یہ الفاظ فرماتے ہوئے آپ نے اپنی دوانگلیاں
کھڑی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر دیں.اس لطیف حدیث کا بھی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میری وفات کے معابعد قیامت آجائے گی کیونکہ یہ
بات نہ صرف واقعات بلکہ آپ کی بعثت کی غرض وغایت کے بھی خلاف ہے کہ آپ کے معا بعد قیامت
آجاوے.پس اس حدیث میں بھی یقیناً یہی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ میرا دور شریعت قیامت تک چلے
گا اور میرے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی جو میری شریعت کو منسوخ کر کے ایک نیا دور شروع کر دے.خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا دادمشن مکانی لحاظ سے وسیع اور غیر محدود
ہے اور دنیا کی کوئی قوم آپ کی دعوت سے باہر نہیں اسی طرح زمانی لحاظ سے بھی آپ کا مشن کسی ایک
زمانہ تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک وسیع اور غیر محدود ہے.اس تمہیدی نوٹ کے بعد جو اسلام کے تبلیغی
نظریہ کی وضاحت کے لئے ضروری تھا ہم اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں.تبلیغی خطوط کے لئے انگوٹھی کی تیاری جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے صلح حدیبیہ کے بعد جب کہ
مکہ والوں کے ساتھ صلح ہو جانے کے نتیجہ میں تلوار کے
جہاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوکسی قدر فرصت حاصل ہوئی تو آپ نے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے
ہوئے پہلا کام یہ کیا کہ اسلام کے عالمگیر مشن کے پیش نظر مختلف حکومتوں کے فرمانرواؤں کی طرف تبلیغی
خطوط بھجوانے کی تجویز کی تا کہ ان فرمانرواؤں اور ان کے ذریعہ ان کی رعایا کو اسلام کا پیغام پہنچایا
بخاری و مسلم
Page 910
۸۹۵
جائے کہ یہی آپ کی بعثت کی اصل غرض و غایت تھی.چنانچہ آپ نے حدیبیہ سے واپس آتے ہی اس بارہ
میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور جب اس مشورہ میں آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ دنیوی حکمرانوں کا یہ عام
دستور ہے کہ وہ مہر شدہ خط کے بغیر کسی اور خط کی طرف توجہ نہیں دیتے تو آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی
تیار کروائی جس میں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کے الفاظ کندہ کروائے گئے.اور خدا تعالیٰ کے نام کو مقدم
اور بالا رکھنے کے خیال سے آپ نے ان الفاظ کی ترتیب یہ مقررفرمائی کہ سب سے اوپر اللہ کا لفظ لکھا گیا
اور درمیان میں رسول کا لفظ کندہ کیا گیا اور سب سے نیچے کی سطر میں محمد کا لفظ رکھا گیا " نیز چونکہ ان
تبلیغی خطوط میں اس انگوٹھی کا نقش لینا مد نظر تھا، اس لئے یہ تدبیر بھی اختیار کی گئی کہ ان الفاظ کوسیدھے
رخ پر لکھنے کی بجائے الٹا لکھا گیا تا کہ جب اس کا نقش لیا جائے تو یہ نقش پریس کی چھپائی کی طرح سیدھی
صورت میں ظاہر ہو..آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگوٹھی اس کے بعد ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہی اور آپ کی وفات
کے بعد اسے حضرت ابوبکر خلیفہ اول نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور حضرت ابو بکڑ کے بعد وہ حضرت عمر خلیفہ ثانی
کے ہاتھ میں رہی اور ان کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ثالث نے اسے پہنائی کہ ایک دن وہ ان کے ہاتھ
سے اریس نامی کنوئیں میں گر کر کھوئی گئی ہے حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں نے تین دن تک اس انگوٹھی
کی تلاش جاری رکھی اور کنوئیں کا سارا پانی نکال کر چھان مارا مگر وہ نہ ملی ھے
فریضہ تبلیغ میں حسن تدبیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر سے جو آپ نے صحابہ کے
مشورہ سے انگوٹھی تیار کرانے میں اختیار کی اس بات پر اصولی روشنی
ل : بخاری جلد ا کتاب العلم صفحه ۱۵ نیز بخاری جلد ۲ کتاب الجہاد صفحه ۱۰۷
: فتح الباری بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۳۴ بروایت اسنوی جس کی تصدیق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط بنام
مقوقس مصر سے بھی ہوتی ہے جو اصلی صورت میں دریافت ہو گیا ہے اور ہم آگے چل کر اسی کتاب میں اس کا فوٹو درج
کررہے ہیں.:۳
زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۳۴.نیز ملاحظہ ہو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط بنام مقوقس مصر کا عکس جو اسی کتاب میں
دوسری جگہ درج کیا گیا ہے جس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ کی تحریر سیدھی نظر آتی ہے جو اس بات کا بین ثبوت
ہے کہ اصل انگوٹھی میں الٹی تحریر تھی.بخاری کتاب اللباس روایت ابن عمرؓ
۵ : مسند احمد بن حنبل
Page 911
۸۹۶
پڑتی ہے کہ آپ کس طرح تبلیغ کے کام میں ان تمام رستوں کو اختیار فرماتے تھے جو مخاطب کو اپنی طرف
مائل کرنے اور اس کے دل پر اچھا اثر پیدا کرنے کے لئے ضروری تھے.ظاہر ہے کہ جہاں تک خالص تبلیغ
کا تعلق ہے کسی مہر کا ہونا یا نہ ہونا ایک بالکل زائد چیز ہے اور کلمہ حق مہر کے بغیر بھی اتنا ہی وزن رکھتا ہے
جتنا کہ مہر کے ساتھ لیکن چونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس زمانہ کے بادشاہ مہر کے بغیر کسی خط کی طرف توجہ
نہیں دیتے اور آپ کسی ایسے پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے مخاطب کے دل میں کسی
جہت سے بے تو جہگی کی صورت پیدا ہو اس لئے آپ نے اس معمولی سی زائد تجویز کو بھی بڑے اہتمام کے
ساتھ اختیار کیا تا کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی ایسا رخنہ نہ رہ جائے جو تبلیغ کے اثر کو کسی جہت سے کمزور کرنے والا
ہو اور یہی اس قرآنی آیت کی عملی تفسیر ہے کہ :
جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
یعنی ”اے رسول دین حق کی تبلیغ کے معاملہ میں ہمیشہ اس رستہ کو اختیار کرو جو مخاطب کے
دل و دماغ پر اثر پیدا کرنے کے لحاظ سے بہترین ہو.“
عرب کے چاروں اطراف میں تبلیغی مہم جوتبلیغی خطوط اس موقع پر روانہ کئے گئے وہ عرب کے
چاروں اطراف کے حکمرانوں کے نام تھے یعنی
شمال میں روما کی مشہور سلطنت کے شہنشاہ قیصر کے نام اور شمال مشرق میں فارس کی مشہور سلطنت کے شہنشاہ
کسری کے نام اور عرب کے شمال مغرب میں مصر کے بادشاہ مقوقس کے نام ے اور مشرق میں یمامہ کے
رئیس ہوذ ہ بن علی کے نام.اور مغرب میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام جو عرب کے مقابل پر براعظم
افریقہ میں ایک عیسائی حکومت تھی.اور شمال میں عرب کی حدود کے ساتھ متصل ریاست غسان کے حاکم
کے نام جو قیصر کے ماتحت تھا.اسی طرح آپ نے ایک خط عرب کے جنوب میں یمن کے رئیس کی طرف
بھجوایا تھا اور ایک خط عرب کے مشرق میں بحرین کے والی کی طرف بھی لکھا تھا وغیرہ وغیرہ.اس طرح
ل: سورة النحل : ۱۲۶
مقوقس دراصل مصر کے گورنر کے سرکاری عہدہ کا نام تھا اور ہر گورنر مقوقس کہلاتا تھا.مصر کے یہ گورنر اس زمانہ میں
قیصر روما کے ماتحت ہوا کرتے تھے مگر غالبا یہ ایک موروثی عہدہ تھا جو سوائے خاص حالات کے ایک ہی مخصوص خاندان
میں ورثہ کے طور پر قائم چلا جاتا تھا.عرب لوگ ایسے فرمانرواؤں کو بھی ملک یعنی بادشاہ کہہ کر پکارتے تھے.ابن ہشام وطبری.نیز زرقانی جلد ۳ و تاریخ خمیس جلد۲ نیز لائف آف محمد مصنفہ میور
Page 912
۸۹۷
گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے چاروں اطراف میں اسلام کا پیغام پہنچا کر فریضہ تبلیغ ادا کیا
لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ یہ سارے خطوط صلح حدیبیہ کے معابعد ایک ہی وقت میں روانہ کئے گئے تھے
کیونکہ ممکن ہے کہ بعض تو ایک ہی وقت میں روانہ کئے گئے ہوں اور بعض ایک دوسرے سے کچھ وقفہ پر
بھجوائے گئے ہوں مگر بہر حال یہ بات یقینی ہے کہ ان کا سلسلہ صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا اور غالبا سب
سے پہلا خط قیصر روما یعنی ہر قل کے نام لکھا گیا تھا اور اسی سے ہم اپنے اس نوٹ کی ابتداء کرتے ہیں.قیصر و کسری کی باہمی کشمکش اور آنحضرت مگر اس خط کا ذکر کرنے سے قبل قیصر وکسرٹی کی
حکومتوں کے متعلق ایک ضمنی نوٹ درج کرنا
صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان پیشگوئی ضروری ہے جیسا کہ سیرۃ خاتم النبین حصہ اول
↓
وحصہ دوم میں بتایا جا چکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے شمال مغرب اور شمال
مشرق میں دو عظیم الشان سلطنتیں پائی جاتی تھیں یعنی ایک روما کی سلطنت تھی جس کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا اور
دوسرے فارس یعنی ایران کی ساسانی سلطنت تھی جس کا بادشاہ کسری کہلاتا تھا.یہ روما کی سلطنت وہی
ہے جو تاریخ میں مشرقی روما کی سلطنت یا دوسرے الفاظ میں بازنطینی حکومت کہلاتی ہے.جسے انگریزی
میں ایسٹرن رومن ایمپائر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے.روما کی مغربی سلطنت کے تنزل کے بعد روما کی
مشرقی سلطنت نے جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا عروج پکڑا اور جس زمانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس زمانہ
میں روما کی مشرقی سلطنت اور کسریٰ کی ایرانی سلطنت دنیا بھر میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ
طاقتور سلطنتیں تھیں.ان دونوں سلطنتوں کی آپس میں بھاری رقابت رہتی تھی کیونکہ سیاسی حسد کے علاوہ
دونوں کا مذہب اور تمدن بھی جد الجد اتھا.یعنی جہاں روما کی سلطنت عیسائی مذہب کی پیر تھی وہاں فارس کی
ساسانی سلطنت آتش پرست اور مشرک تھی.اور جیسا کہ کتاب ہذا کے حصہ اول و دوم میں بیان کیا جاچکا
ہے.اس زمانہ میں ان دونوں حکومتوں کے درمیان جنگ شروع تھی اور فارس کے کسری نے روما کے قیصر
کو اوپر تلے شکستیں دے کر اس کا بہت سا علاقہ چھین لیا ہوا تھا چونکہ مکہ والے بھی مشرک اور بت پرست
تھے اس لئے انہیں طبعا اس جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی تھی لیکن مسلمان حضرت عیسی
: میور صفحات ۲۸۵،۲۸۴
: میور صفحات ۱۷۳،۱۷۲
BYZANTINE :✓
نیز دیکھئے لائف آف محمد مصنفہ سرولیم ایڈیشن ۱۹۲۳ء صفحات ۱۲۳،۱۲۲ و صفحات ۳۶۹،۳۶۸
Page 913
۸۹۸
پر ایمان لانے کی وجہ سے عیسائیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتے تھے.یہ وہ وقت تھا کہ جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر وہ پیشگوئی فرمائی جو قرآن شریف کی سورۃ روم کے شروع
میں بیان ہوئی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں:
غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي
بِضْعِ سِنِينَ لِلهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ
اللَّهِ
يَنْصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) وَعْدَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ )
یعنی رومی لوگ قریب ترین زمین میں مغلوب کئے گئے لیکن وہ اپنی مغلوبی کے بعد
عنقریب غالب آئیں گے.یہ تغیر نو سالوں کے اندر اندر ہوگا.اور اس سے پہلے اور اس کے بعد
اصل حکومت تو صرف خدا ہی کی ہے.( یعنی اس سے پہلے روحانی حکومت خدا کی ہے اور اس کے
بعد ظاہری حکومت بھی اسلام کے غلبہ کے ذریعہ خدا ہی کی ہونے والی ہے ) اور اس دن مومن
خوش ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے.وہ مدددیتا ہے جسے چاہتا ہے کیونکہ وہ طاقتور اور رحیم خدا
ہے.یہ خدا کا پختہ وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے.“
یہ قرآنی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تشریف رکھتے تھے
اور کسریٰ کی فتوحات کا سیلاب پورے زور میں تھا حتی کہ وہ قیصر کا بہت سا علاقہ چھین کر اور شام
اور مصر اور ایشیائے کو چک کو تاراج کر کے قیصر کے دارالسلطنت قسطنطنیہ کے دروازے کھٹکھٹا رہا تھا مگر
اس قرآنی پیشگوئی کے مطابق جنگ نے اچانک پلٹا کھایا اور چند سال کی جدوجہد کے بعد قیصر کی فوجوں
نے نہ صرف اپنا سارا علاقہ واپس چھین لیا بلکہ کسری کے علاقہ میں بھی یلغار کرتی ہوئی گھس گئیں.یہ وہ
عظیم الشان پیشگوئی تھی جس کی صداقت کو غیر مسلم مؤرخین بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں چنانچہ
ان واقعات کے متعلق سرولیم میورلکھتا ہے :
قریب قریباً اس زمانہ سے لے کر جب کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے نبوت کا دعوی کیا
روما اور فارس کی حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف ایک خونی جنگ لڑ رہی تھیں.۶۲۱ عیسوی تک
: سورة الروم : ۳ تا ۷
بضع کا لفظ عربی زبان میں تین سے لے کر نو سال تک کے عرصہ کے لئے آتا ہے (اقرب الموارد)
Page 914
۸۹۹
اس جنگ میں کسری کی فوجوں کو مسلسل فتح حاصل ہوتی گئی.شام، مصر اور ایشیائے کو چک یکے
بعد دیگرے تاراج کئے گئے اور خود قسطنطنیہ کا شہر بھی خطرہ میں پڑ گیا.بالآخر ہر قل (شہنشاہ روم )
اپنی غفلت سے بیدار ہوا اور محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی ہجرت از مکہ کے زمانہ میں وہ دشمن کی
فوجوں کو ایشیائے کو چک کی قلعہ بندیوں سے پسپا کر رہا تھا.اس جنگ کی دوسری مہم میں قیصر اپنی
فاتح افواج کے ساتھ یلغار کرتا ہوا کسری کے علاقہ کے اندر گھس گیا.166
اس جنگ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی ہمدردی اور دعا قیصر کے حق میں تھی.مسیحیت
ایک الہامی مذہب تھا جس کی اسلام کے ساتھ صلح ممکن تھی مگر ایران کے آتش پرست مشرک
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے خیالات سے کوئی نسبت نہیں رکھتے تھے.بہر حال ابھی کسری کی
فاتح فوجیں قیصر کے خلاف پیہم غلبہ پاتی جارہی تھیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن کی
تیسویں سورت ( سورۃ روم ) میں یہ حکیمانہ پیشگوئی بیان کی کہ غُلِبَتِ الرُّومُ لى فِي أَدْنَى
الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ آلاية ( یعنی عنقریب
روما کو غلبہ حاصل ہوگا ) اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ پیشگوئی بعد کے واقعات کے مطابق
،،
ٹھیک نکلی.قیصر کی ان غیر معمولی فتوحات کا زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کے ساتھ شروع
ہوا اور مسلمانوں کو قیصر کی پہلی فتح کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ قریش مکہ کے خلاف بدر کے میدان
میں نمایاں فتح حاصل کر کے مدینہ کو واپس لوٹے تھے..اور کسری کے خلاف قیصر کو آخری اور فیصلہ کن فتح
صلح حدیبیہ کے زمانہ کے قریب حاصل ہوئی.سے
اپنی اس غیر معمولی فتح کی خوشی اور شکرانہ میں قیصر نے حمص سے لے کر ایلیا ( یعنی یروشلم یا بیت المقدس)
تک کا پیدل سفر کیا.دراصل ہر قل کا یہ سفر ایک نذر کی ایفا میں تھا جو اس نے فتح حاصل ہونے کی صورت
میں مانی ہوئی تھی چنانچہ وہ ایڈیسا ک سے لے کر یروشلم تک پیدل گیا جہاں حضرت
مسیح ناصری کی اصلی صلیب
لائف آف محمد مصنفه میور صفحه ۳۶۸
س ترمذی جلد۲ تفسیر سورة روم
HIMS AR EMESA :
لائف آف محمد مصنفه میور صفحه ۱۲۳،۱۲۲
لائف آف محمد مصنفہ میور صفحه ۳۶۸، ۳۶۹
بخاری جلد ۲ کتاب الجہاد صفحہ ۱۰۷
ك : EDESSA مگر غالباً یہ امیسا (EMESA) یعنی جمع ہے اور غلطی سے ایڈیسا لکھا گیا ہے جو ایک دوسرا شہر ہے.
Page 915
۹۰۰
جواہل فارس سے واپس چھینی گئی تھی اپنی جگہ پر دوبارہ رکھی جانے والی تھی اور یہ سفر اس شان سے کیا گیا کہ
رستہ میں ہر قل جہاں جہاں سے گزرتا تھاز مین پر فرش اور فرش کے اوپر پھولوں کی سیج بچھائی جاتی تھی.ہر قل کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی محط صلح حد جہیہ کے بعد خانہ سب سے پہلا
حدیبیہ
تبلیغی خط ہرقل کے قیصر روما کے نام
بھجوایا گیا.یہ خط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معا بعد ماہ ذوالحجہ 4 ہجری میں روانہ کیا.اور اس
خدمت کے لئے آپ نے اپنے ایک ہوشیار اور مخلص صحابی دحیہ بن خلیفۃ الکلبی کو منتخب فرمایا جو اس سے
پہلے بھی شام کی طرف سفر کر چکے تھے اور اس علاقہ کے واقف تھے.دحیہ ایک خوشرو نو جوان تھے جن کی شکل
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کشفی طور پر حضرت جبرائیل کو بھی دیکھا تھا.اور آپ نے اس
خط کے بھجواتے ہوئے یہ امید ظاہر فرمائی تھی کہ دحیہ یا جو شخص بھی یہ خدمت بجالائے گا خواہ وہ بظاہر اس
مہم میں کامیاب ہو یا نہ ہو وہ انشاء اللہ ضرور جنت میں جائے گا.اس تبلیغی خط کی تیاری اور مہر وغیرہ
لگانے کے بعد آپ نے دحیہ کو ہدایت فرمائی کہ میرا یہ خط پہلے بصری کے رئیس کے پاس لے جاؤ ( جو عرب
کے شمال میں قیصر کی طرف سے گویا موروثی گورنر یا حاکم تھا) اور پھر اس کے توسط سے قیصر کے پاس پہنچو 2
اس وقت بصری کا گورنر حارث بن ابی شمر تھا جو اس علاقہ میں ریاست غسان کا والی اور حکمران تھا.بصری کے گورنر یعنی ملک غسان کا واسطہ اختیار کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دانش
مندی اور حسن تدبیر کا ثبوت دیا جو آپ اس سے قبل انگوٹھی کے تیار کرانے میں ظاہر فرما چکے تھے.کیونکہ
غالباً آپ قیصر وکسریٰ کے درباروں کے متعلق یہ بات سن چکے تھے کہ یہ لوگ اپنی دنیوی بڑائی اور
علومر تبت کی وجہ سے عموماً کوئی چھٹی براہ راست وصول نہیں کرتے جب تک کہ وہ علاقہ کے گورنر یا رئیس
کے توسط سے نہ آئے اور چونکہ آپ کی اصل غرض کلمہ حق کی تبلیغ تھی اس لئے آپ نے ان درباری آداب کو
لائف آف محمد مصنفہ میور صفحه ۳۶۹
HERACLIUS :
۵ شمائل ترمندی و مسند احمد جلد ۲ صفحه ۱۰۷
ابن اسحاق بحوالہ زرقانی جلد ۲ صفحه ۳۳۵
ابن سعد حوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۳۴، ۳۳۷
زرقانی
کے یہ عرب کے شمال اور شام کے جنوب میں ایک شہر تھا جسے انگریزی میں BOSRA کہتے ہیں.اسے عراق کے
جدید شہر بصرہ کے ساتھ خلط نہیں کرنا چاہئے.بخاری کتاب الجہاد باب دعا النبی الی الاسلام زرقانی جلد ۲ صفحه ۳۳۵
Page 916
۹۰۱
ملحوظ رکھنا ضروری خیال کیا تا کہ ان کی وجہ سے اصل کام میں کوئی روک نہ پیدا ہو سکے.ضمنا آپ کی یہ
نیت بھی ضرور ہوگی کہ اس طرح اصل مخاطب کے علاوہ ایک درمیانی رئیس تک بھی آپ کا پیغام پہنچ جائے
گا اور جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے یہی طریق آپ نے مملکت فارس کے کسری کے متعلق اختیار کیا
جسے مراسلہ بھجواتے ہوئے آپ نے اپنے اپچی کو ہدایت فرمائی تھی کہ پہلے یہ خط بحرین کے رئیس کے پاس
لے جانا اور پھر اس کے توسط سے کسریٰ کے پاس پہنچنا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکیمانہ فعل جہاں
ایک طرف آپ کے حزم واحتیاط اور حسن تدبیر کی دلیل ہے وہاں وہ اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ دنیوی
حکمرانوں کے جائز آداب ملحوظ رکھنا نبوت کی شان کے منافی نہیں.یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بھجوایا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ:
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَرُ اَوْ يَخْشُى O
یعنی " فرعون کے پاس جا کر اس کے ساتھ نرم انداز پر گفتگو کرنا شاید وہ اسی طرح نصیحت
حاصل کرلے اور خدا سے ڈرنے کا رستہ اختیار کرلے.“
غالبا ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر قل کے نام خط روانہ کرنے کی تیاری ہی فرمارہے تھے کہ ایک
غیبی نصرت کے ماتحت ہر قل کو خود بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف توجہ پیدا ہوگئی.کیونکہ
بخاری میں روایت آتی ہے جو اغلباً اسی موقع سے تعلق رکھتی ہے کہ جو نہی شہنشاہ ہر قل ایلیا میں آیا کے تو ایک
صبح کو وہ بہت پریشان خاطر اور گھبرایا ہوا نظر آتا تھا جس پر اس کے بعض مذہبی درباریوں نے اس سے عرض
کیا کہ آج آپ کی حالت کچھ پریشان نظر آتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے آج رات ستاروں
میں غور کر کے ( ہر قل علم ہیئت میں کافی دسترس رکھتا تھا) معلوم کیا ہے کہ کسی ختنہ کرنے والی قوم میں ایک
نئے بادشاہ کا ظہور ہوا ہے.اور اس نے پوچھا کہ آج کل کون کون سی قوم ختنہ کرتی ہے؟ اس کے درباریوں
نے جواب دیا کہ ہمارے علم میں تو یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا اور آپ کو یہودیوں کی وجہ سے
پریشان نہیں ہونا چاہئے.آپ اپنی حکومت کے مختلف شہروں میں حکم بھجوادیں کہ یہود کو قتل کرنا شروع کر دیا
بخاری کتاب العلم و کتاب الجہاد
: ایلیا بیت المقدس یعنی یروشلم کا پرانا نام ہے اور غالباً یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے کیونکہ عبرانی میں ایل خدا کو کہتے ہیں
گویا ایلیا کے معنے خدا کی طرف منسوب ہونے والے شہر یا بالفاظ دیگر مقدس شہر کے ہیں اور یہی بیت المقدس کے لفظ
کا مفہوم ہے
: سورة طا : ۴۵
Page 917
۹۰۲
جائے لیکن ابھی یہ معاملہ اسی مرحلہ پر تھا کہ ہر قل کو ریاست غسان کے رئیس کی طرف سے یہ اطلاع پہنچی کہ
عرب میں ایک شخص محمد نامی (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اسے ملک میں کامیابی ہورہی
ہے.ہرقل نے اس خبر کے سننے پر ہدایت دی کہ فوراً معلوم کیا جائے کہ آیا عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں
یا نہیں.جس پر اسے بتایا گیا کہ عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں.ہر قل نے بے ساختہ کہا.تو پھر یہی اس امت
کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے اور ہرقل نے مزید احتیاط کے طور پر اپنے ایک رفیق کو جو ایک بڑا عالم انسان تھا
رومیہ میں خط لکھا اور اس معاملہ میں اس کی بھی رائے پوچھیے
لیکن اس عرصہ میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خط ہرقل کو پہنچ گیا اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ
ہم اس جگہ بخاری کے الفاظ میں ہی یہ روایت درج کر دیں کیونکہ وہی اس تعلق میں صحیح ترین اور مفصل ترین
روایت ہے.سوعبداللہ بن عباس جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے بیان کرتے ہیں کہ :
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کی طرف اسلام کی دعوت کا خط لکھا اور اپنا یہ خط دحیہ کلبی کے
ہاتھ بھجوایا اور آپ نے دحیہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ آپ کے اس خط کو بصری کے رئیس کے پاس لے جائیں
تا کہ وہ اسے آگے قیصر کے پاس بھجوا دے.اس زمانہ میں قیصر روما سلطنت فارس کے خلاف فتح پانے کے
شکرانے میں حمص سے ایلیا کی طرف پیدل چل کر آیا تھا اور ایلیا ( بیت المقدس ) میں ہی آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا یہخط قیصر کو پہنچا.قیصر نے جب خط کو پڑھا تو ہدایت دی کہ اگر اس مدعی رسالت کی قوم کا کوئی
شخص یہاں موجود ہو تو اسے تلاش کر کے پیش کیا جائے.ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابوسفیان سے معلوم
ہوا ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے بعض قریش ساتھیوں کے ساتھ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا
اور یہ صلح حدیبیہ -
احدیبیہ کے بعد کا زمانہ تھا.ابوسفیان نے بتایا کہ قیصر کے آدمی ہمیں تلاش کر کے ایلیا میں لے گئے
اور قیصر کے سامنے پیش کیا.اس وقت قیصر اپنی پوری شان کے ساتھ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سر پر
حکومت کا تاج تھا اور اس کے اردگر دروما کے بڑے بڑے درباری موجود تھے.قیصر نے اپنے ترجمان
سے کہا کہ ان عرب لوگوں سے پوچھو کہ اس مدعی رسالت کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے.ابوسفیان نے
عرض کیا میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں اور وہ رشتہ میں میرے چا کا بیٹا ہے.ابوسفیان بیان کرتا ہے کہ قیصر نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھیوں کو اپنے سامنے مگر میری پیٹھ کی
طرف کھڑا کر دیا.پھر اس نے ترجمان سے کہا کہ اس کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ میں اس سے اس شخص کے
ا بخاری باب کیف کان بداء الوحی
Page 918
٩٠٣
متعلق بعض سوالات کرنا چاہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے.پس اگر ابوسفیان اپنے جواب میں کوئی
بات غلط بیان کرے تو تم مجھے فوراً بتا دینا ( ابوسفیان کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ میرے
ساتھی یہ محسوس کریں گے میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو میں اس موقع پر ضرور کوئی نہ کوئی غلط بات کہہ جا تا مگر
میں بچی سچی بات کہنے پر مجبور ہو گیا ) اس کے بعد قیصر نے ترجمان کے ذریعہ اپنے سوالات شروع کئے.قیصر.اس مدعی کا تمہاری قوم میں حسب نسب کیا ہے؟
ابوسفیان.وہ ہم میں اچھے نسب کا ہے اور شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے.قیصر.کیا اس سے پہلے تم میں سے کسی شخص نے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے؟
ابوسفیان نہیں.قیصر.کیا اس دعوئی سے پہلے تم نے مدعی کے خلاف کبھی جھوٹ کا الزام لگتے سنا ہے؟
ندگی کے خلاف یہ
ابوسفیان نہیں.قیصر.کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟
ابوسفیان نہیں.قیصر.کیا اس مدعی کو بڑے بڑے لوگ مان رہے ہیں یا کہ کمزور اور غریب مزاج لوگ؟
ابوسفیان.کمزور اور غریب لوگ.قیصر.کیا اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہور ہے ہیں؟
ابوسفیان.بڑھ رہے ہیں.قیصر.کیا ان میں سے کبھی کوئی شخص اس کے دین کو بُرا سمجھتے ہوئے مرتد ہوا ہے؟
ابوسفیان نہیں.قیصر.کیا یہ شخص کبھی اپنے عہد کو تو ڑتا ہے؟
ابوسفیان نہیں.لیکن آج کل ہمارا اور اس کا ایک معاہدہ چل رہا ہے اس کے متعلق ہمیں ڈر ہے
اور نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر کیا ہو گا.(ابوسفیان کہتا ہے کہ مجھے اس موقع پر اس فقرہ کے سوا کوئی اور موقع
نہیں مل سکا کہ میں اپنی طرف سے آپ کے خلاف کوئی بات لگا سکوں )
قیصر.کیا کبھی اس کے ساتھ تمہاری کوئی جنگ ہوئی ہے؟
ابوسفیان.ہاں جنگ ہوئی ہے.
Page 919
۹۰۴
قیصر.پھر اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا رہا ہے؟
ابوسفیان.یہ جنگ ایک اوپر چڑھنے والے اور نیچے گرنے والے ڈول کی طرح رہی ہے کہ کبھی اسے
غلبہ ہو جاتا ہے اور
کبھی ہمیں.قیصر.یہ مدعی تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟
ابوسفیان.وہ کہتا ہے کہ خدا کو ایک سمجھو اور شرک نہ کرو اور وہ ہمیں اپنے باپ دادوں والی عبادت
سے روکتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھو اور صدقہ دو اور برائیوں سے بچ کر رہو اور اپنے عہدوں کو پورا کرو اور
امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو.اس سوال وجواب کے بعد قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہو کہ جب تم سے میں نے
اس شخص کے حسب نسب کے متعلق پوچھا تھا تو تم نے جواب دیا تھا کہ وہ شریف خاندان سے ہے اور خدا
کے رسول ہمیشہ شریف خاندانوں میں سے مبعوث کئے جاتے ہیں.پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس
سے پہلے تم میں سے کسی شخص نے کبھی ایسا دعویٰ کیا ہے تو تم نے یہ جواب دیا کہ نہیں.یہ میں نے اس لئے
پوچھا تھا کہ اگر کسی اور نے ایسا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ شاید یہ اس کی نقل کر رہا ہے.پھر میں نے
تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے اس کے دعوئی سے پہلے کبھی کسی بات میں اس کا جھوٹ دیکھا تو تم نے کہا کہ
نہیں.تو میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جوشخص انسانوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا
ہے.پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے اور تم نے کہا کہ
نہیں.یہ میں نے اس لئے پوچھا تھا کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ خیال کیا
جاسکتا تھا کہ شاید وہ اپنے خاندان کی کھوئی ہوئی بادشاہت کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہے.پھر میں نے تم
سے پوچھا تھا کہ کیا اسے بڑے بڑے لوگ مان رہے ہیں یا کہ کمزور اور غریب مزاج لوگ.اور تم نے
جواب دیا کہ کمزور اور غریب مزاج لوگ مان رہے ہیں اور حق یہ ہے کہ ( شروع شروع میں ) خدا کے
رسولوں کو کمزور اور غریب مزاج لوگ ہی مانا کرتے ہیں.پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے ماننے
والے زیادہ ہو رہے ہیں یا کہ کم ہو رہے ہیں؟ اور تم نے یہ جواب دیا کہ زیادہ ہور ہے ہیں اور ایمان کا
یہی حال ہوا کرتا ہے کہ جب تک کہ وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچ جاتا وہ برابر ترقی کرتا چلا جاتا ہے.پھر میں
نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کبھی کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اس کے دین کو نا پسند کرنے کی وجہ سے مرتد
ہوتا ہے.تم نے کہا نہیں اور یہی بچے ایمان کا حال ہوتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ دل میں داخل ہو جائے
Page 920
تو کوئی شخص ( خواہ کسی اور وجہ سے مرتد ہو جائے تو ہو جائے مگر اسے برا سمجھ کر پیچھے نہیں ہٹتا.پھر میں نے تم
سے پوچھا تھا کہ کیا کبھی یہ شخص بد عہدی کرتا ہے.اور تم نے کہا کہ نہیں.اور خدا کے رسولوں
کا یہی مقام ہوتا
ہے کہ وہ کبھی بدعہدی نہیں کرتے.پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی
جنگ ہوئی ہے اور تم نے اس کا جواب دیا کہ ہاں ہوئی ہے اور یہ کہ کبھی لڑائی میں اسے غلبہ ہو جاتا ہے
اور کبھی ہمیں ہو جاتا ہے.اور یہی خدا کے رسولوں کا حال ہوتا ہے کہ ان کی جماعتوں پر بھی کبھی کبھی تکلیفیں
آتی رہتی ہیں مگر انجام بہر حال ان کے حق میں ہوتا ہے اور آخر کا روہی جیتے ہیں.پھر میں نے تم سے پوچھا
تھا کہ وہ تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے اور تم نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کو ایک مانو.شرک نہ کرو، نماز پڑھو،
صدقہ دو، بری باتوں سے پر ہیز کرو، اپنے عہدوں کو پورا کرو اور امانتوں میں خیانت نہ کرو اور یہی ایک نبی
کے اوصاف ہوا کرتے ہیں.اس کے بعد قیصر نے کہا.میں جانتا تھا کہ عنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے لیکن اے عرب کے
لوگو! میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا.اور اگر وہ باتیں جو تم نے مجھ سے بیان کی ہیں درست ہیں تو
میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں کہ یہ شخص اس زمین پر جو اس وقت میرے ان دو قدموں کے نیچے ہے
ضرور قابض ہو کر رہے گا.اور اگر مجھے توفیق ملے تو میں اس کی ملاقات کے لئے پہنچوں اور اگر میں اس کے
پاس پہنچوں تو اس کے قدموں کو دھو کر راحت پاؤں.ابوسفیان کہتا ہے کہ اس کے بعد قیصر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے دربار میں
پڑھے جانے کا حکم دیا.اس خط میں یہ عبارت
لکھی تھی.بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرُسُولِهِ إِلَى هِرْقَلَ عَظِيمٍ
الرُّومِ.سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى اَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى اَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ تُسْلَمُ
وَأَسْلِمُ يُوتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ.فَإِن تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْإِرْيُسِيِّينَ.وَيَا أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ
(ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ اس خط کو شروع کرتا ہوں جو بے مانگے رحم کرنے والا
اور اعمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے.یہ خط محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول کی طرف
سے روما کے رئیس ہرقل کے نام ہے.سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے.اس کے
Page 921
بعداے رئیس روما! میں آپ کو اسلام کی ہدایت کی طرف بلاتا ہوں.مسلمان ہوکر خدا کی سلامتی
کو قبول کیجئے کہ اب یہی صرف نجات کا رستہ ہے.اسلام لائیے خدا تعالیٰ آپ کو اس کا دوہرا
اجر دے گا لیکن اگر آپ نے روگردانی کی تو یا درکھیئے کہ آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ کی گردن
پر ہوگا اور اے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف تو آجاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے
یعنی ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرا ئیں اور
خدا کو چھوڑ کر اپنے میں سے کسی کو اپنا آقا اور حاجت روانہ گردا نہیں پھر اگر ان لوگوں نے
روگردانی کی تو ان سے کہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو بہر حال خدائے واحد کے دامن کے ساتھ وابستہ
اور اس کے فرمانبردار بندے ہیں.)
ابوسفیان روایت کرتا ہے کہ جب یہ گفتگو اور اس خط کا پڑھا جا ناختم ہوا تو دربار میں ہر طرف سے رومی
رئیسوں کی آواز میں بلند ہونی شروع ہوئیں اور آپس کا کلام اونچا اور خلط ملط ہونے لگا اور میں نہیں سمجھتا تھا
کہ وہ کیا کہ رہے ہیں.اس وقت ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم باہر چلے جائیں اور جب میں اپنے ساتھیوں کے
ساتھ باہر آیا اور مجھے ان کے ساتھ علیحدگی میں بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ محمد
کا ستارہ تو بہت بلند ہوتا نظر آتا ہے کیونکہ روما کی حکومت کا بادشاہ اس سے خوف کھا رہا ہے.اس کے بعد میں
ہمیشہ اپنے آپ
کو نیچا اور ہیٹا محسوس کرتا رہا.اور میرا دل اس یقین سے پر تھا کہ محمد اب غالب ہوکر رہے گا.حتی کہ میرے دل میں اسلام کی صداقت نے رستہ پا لیا حالانکہ میں اس سے پہلے اسے پسند نہیں کرتا تھا.اسی سے ملتی جلتی روایت بخاری باب كَيْفَ كَانَ بَدأُ الْوَحِی میں بھی آتی ہے اور طبری اور ابن
اسحاق اور دوسرے سب مؤرخوں کی روایتیں بھی خفیف لفظی فرق کے ساتھ اس کی مؤید ہیں اور یکجائی بیان
کے لئے فتح الباری اور تاریخ خمیس اور زرقانی کا کوئی جواب نہیں.گواس موقع پر اپنے معزز درباریوں اور خصوصاً مذہبی لیڈروں کی مخالفت کی وجہ سے ہرقل خائف
ہو کر خاموش ہو گیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط اور اس سے قبل
اور بعد کے حالات کا گہرا اثر ہو چکا تھا کیونکہ جب وہ ایلیا سے لوٹ کر دوبارہ حمص کی طرف گیا اور اس
عرصہ میں اس کو رومیہ کے عالم کا جواب بھی موصول ہو چکا تھا جس میں اس نے ہر قل کی رائے کی تصدیق
ل اریس (جس کی جمع اریسیین ہے) کے معنی کا شتکار اور زمیندار کے ہیں اور اس جگہ اس سے رعایا مراد ہے
بخاری کتاب الجہاد باب دعاء النبی الی الاسلام
Page 922
9+2
کی تھی کہ اس زمانہ میں ایک نبی کا مبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے تو ہر قل نے ایک دفعہ پھر مملکت روم کے بڑے
بڑے اہل الرائے لوگوں کو دعوت دے کر بلایا اور اپنے حمص کے شاہی محل میں انہیں جمع کر کے راز داری
کے خیال سے دربار کے تمام دروازے بند کر وا دیئے اور پھر رؤساء روما کو مخاطب کر کے ان سے کہا کہ اے
میری مملکت کے سردارو! اگر تمہیں اپنی فلاح اور بہبودی منظور ہے اور تم تباہی سے بیچ کر ترقی کا رستہ دیکھنا
چاہتے ہو اور اپنے ملک کو ہلاکت سے بچانے کے خواہاں ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس نبی کوقبول
کر لو جو عرب کی سرزمین میں مبعوث ہوا ہے.قیصر کی یہ بات سن کر اس کے درباری اس طرح بپھرے جس
طرح کہ جنگل میں گورخر بپھرتا ہے.اور قیصر کی مجلس سے بھاگ کر دروازوں سے باہر نکل جانا چاہا لیکن
قیصر کی دور اندیشی نے پہلے سے دروازے بند کر وار کھے تھے اس نے فوراً ان متکبر رئیسوں اور پادریوں
کو واپس بلایا اور ان سے محبت کے انداز میں کہا کہ میں تو صرف تمہارے دین کا امتحان لیتا تھا اور شکر ہے
کہ تم پختہ نکلے.جب قیصر کے درباریوں نے اپنے بادشاہ میں یہ تبدیلی دیکھی تو وہ خوش ہو گئے اور
خوشی کے جوش میں اس کے سامنے سجدہ میں جا گرے.پس یہ وہ انجام تھا جس کو ہر قل شہنشاہ روم اپنی زندگی
کے اس بھاری امتحان میں پہنچا.یہ بات بھی یا درکھنی چاہئے کہ ہر قل نے ایلیا کے دربار میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا
تھا تو دراصل یہ دوسری بار کا پڑھنا تھا.ورنہ اس سے پہلے وہ ایک پرائیوٹ مجلس میں اس خط کو اپنے طور پر
پڑھ چکا تھا.اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ جب پہلی دفعہ قیصر کو آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو
اس نے اپنی پرائیوٹ مجلس میں دحیہ کو بلایا اور اپنے چند مصاحبوں اور عزیزوں کے سامنے اس خط کو پڑھنا
چاہا.اس وقت غالباً یہ خط پہلے ہر قل کے بھتیجے کے ہاتھ میں گیا اور اس نے ہر قل کے سامنے پیش کرنے
سے قبل اس خط کو خود کھول کر دیکھنا چاہا اور خط دیکھتے ہی چلا اٹھا کہ یہ خط تو ہرگز قبول کرنے کے قابل
نہیں کیونکہ اس میں شروع میں آپ کے نام کی بجائے لکھنے والے نے اپنا نام لکھا ہے.جو آپ کی ہتک
بخاری جلد ا باب کیف کان بداء الوحی و زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۳۹
: فتح الباری و زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۳۹
:
ایک روایت میں بھائی کا نام آتا ہے.واللہ اعلم
غالباً اس وقت درباروں میں یہ دستور ہوگا کہ رئیس کو مخاطب کرتے ہوئے از طرف فلاں بنام فلاں“ کی
بجائے ” بنام فلاں از طرف فلاں“ کے الفاظ لکھتے ہوں گے.مگر جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
از طرف محمد رسول اللہ بنام ہرقل عظیم الروم کے الفاظ لکھے تھے.
Page 923
۹۰۸
ہے اور اسی طرح آپ کو شہنشاہ روم لکھنے کی بجائے رئیس روما لکھا ہے اور یہ دوسری ہتک ہے لیکن ہرقل نے
اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ ایک مدعی رسالت کی طرف سے خط آئے اور
میں اسے پڑھے بغیر پھینک دوں؟ اور شاہ روما کی بجائے ”رئیس روما‘ کے الفاظ لکھنے میں کوئی بات
نہیں ہے کیونکہ اصل بادشاہت تو خدا ہی کی ہے اور میں اور یہ مدعی دونوں اسی کے بندے ہیں.یہ کہہ کر
اس نے اپنے بھتیجے کے ہاتھ سے خط لے لیا اور حکم دیا کہ پبلک دربار سے قبل دحیہ کلبی کو سر کاری مہمان کے طور
پر رکھا جائے یا مگر بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ ہر قل کو اپنی بہت سی خوبیوں اور دانائیوں اور دور اندیشیوں
کے باوجود دنیا کے خوف اور طاقت وعزت کی ہوس کی وجہ سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور گویا ایمان کی
چنگاری اس کے سینہ میں روشن ہوتے ہوتے بجھ کر رہ گئی.لیکن معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اس انکار اور محرومی کے اس کے دل کی گہرائیوں میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی عزت گھر کر چکی تھی.چنانچہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
تبلیغی خط کو ایک تبرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھا.اور وہ کئی سو سال تک اس کے خاندان میں محفوظ
رہا.چنانچہ روایت آتی ہے کہ جب شاہ منصور قلاون ( جو ساتویں صدی ہجری میں گزرا ہے ) کے بعض سفیر
ایک دفعہ ملک الفرنج کے پاس گئے تو اس وقت ملک مذکور نے انہیں دکھانے کے لئے ایک سنہری ڈبہ
منگوایا اور اس کے اندر سے ایک ریشمی رومال میں لپٹا ہوا خط نکال کر انہیں دکھایا کہ میرے ایک دادا ہر قل
کے نام آپ کے رسول کا ایک خط آیا تھا وہ آج تک ہمارے گھر میں ایک متبرک تحفہ کے طور پر محفوظ ہے..اگر شاہ منصور قلاون کے مزید حالات دیکھنے ہوں تو انسائیکلو پیڈیا آف اسلام " میں دیکھے جائیں.ہر قل والے خط کے تعلق میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب پہلی دفعہ دحیہ کلبی قیصر کے سامنے پیش
ہونے لگے تو ان سے کہا گیا کہ یہاں کا درباری آداب یہ ہے کہ قیصر کے سامنے جاتے ہی سجدہ میں
گر جاتے ہیں اور پھر جب تک وہ خود نہ کہے سر نہیں اٹھاتے.دحیہ نے کہا میں تو خدا کے سوا کسی کو سجدہ
نہیں کر سکتا خواہ مجھے اس کے سامنے جانے کا موقع ملے یا نہ ملے.مگر پھر خدا نے ایسا فضل کیا کہ وہ اس
خلاف اسلام حرکت کرنے کے بغیر ہی قیصر کے دربار میں باریاب ہو گئے.هے
ل : مواہب اللہ نیر وزرقانی
ے فتح الباری بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۴۲ ،۳۴۳
۵ : تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۳۵
کتاب الاموال بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۴۲ نیز دیکھو صفحه ۳۳۹
: جلد ۲ صفحه ۶۸۵ تا ۶۸۷
Page 924
٩٠٩
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط بنام ہر قل میں ایک بات ایسی ہے جس کی بنا پر بعض عیسائی مؤرخین
نے اعتراض کیا ہے اور اس کی وجہ سے خط کی صداقت کے متعلق بھی شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے.اعتراض یہ ہے کہ خط میں جو یہ الفاظ آتے ہیں کہ یاهْلَ الْكِتُبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الآیة.یہ سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور روایات سے
ثابت ہے کہ سورۃ آل عمران کی ابتدائی اسی آئیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب 9 ہجری میں نجران کے
عیسائیوں کا وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا.اور چونکہ قیصر کے نام کا خط بہر حال
صلح حدیبیہ کے معا بعد کا ہے اس لئے 9 ہجری میں نازل ہونے والی آیت ۶ ہجری یا ۷ ہجری میں لکھے جانے
والے خط کا حصہ نہیں بن سکتی تھی.لہذا ثابت ہوا کہ یہ خط کا قصہ سرے سے ہی درست نہیں ہے.یہ وہ
اعتراض ہے جو اس موقع پر کیا گیا ہے.مگر یہ اعتراض کوئی نیا اعتراض نہیں خود مسلمان مؤرخوں کے سامنے
یہ سوال آیا اور انہوں نے بڑی مفصل بحث کر کے اس کا جواب دیا ہے.دراصل بات یہ ہے اور کئی دفعہ ایسا
ہوا ہے کہ بعض کلمات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عمر کی زبان سے نکلے اور پھر کچھ عرصہ بعد اسی کے
مطابق قرآنی آیات کا نزول ہو گیا.اور یہ صورت اعلیٰ درجہ کے تربیت یافتہ روحانی قلوب کے متعلق ہرگز
بعید از قیاس نہیں کہ وہ اپنے خاص نو ر قلب یا مخصوص روحانی جس کی وجہ سے ایک الہامی صداقت کے نزول
سے قبل ہی ان کی مخفی تاروں سے متاثر ہو کر اس کا اظہار کر دیں.چنانچہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک
اور منافقین کی نماز جنازہ اور شراب کی حرمت اور احکام پردہ وغیرہ کے متعلق اس قسم کے متعدد واقعات
تاریخ اور حدیث میں مذکور ہیں.پس یہ ہرگز بعید از قیاس نہیں کہ اس موقع پر بھی یہ عبارت اولاً آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود املاء فرمائی ہو اور پھر بعد میں وہی عبارت قرآنی آیات کی صورت میں نازل
ہوگئی ہو اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سورۃ آل عمران کی شروع کی اسی آمیتیں سب کی سب وفد نجران کے وقت نازل
نہ ہوئی ہوں بلکہ ان میں سے ایک آدھ آیت پہلے نازل ہو چکی ہو ، لیکن اکثریت کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہو کہ
پہلی اتنی آیتیں وفد نجران کے موقع پر نازل ہوئی تھیں.یا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ آیت دو دفعہ نازل ہوئی ہو.ایک دفعہ اوائل ہجرت میں اور دوسری دفعہ 9 ہجری میں وغیرہ وغیرہ.مگر غالبا اس بحث میں سب سے زیادہ یقینی ثبوت اس اصل خط کے دریافت ہو جانے سے ملتا ہے جو
ا: ابن سعد
: فتح الباری و زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۳۸
چنانچہ ملاحظہ ہو فتح الباری و تفسیر ابن کثیر وزرقانی وغیرہ
Page 925
۹۱۰
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانہ میں مقوقس مصر کو لکھ کر بھیجا.یہ خط اپنی اصلی صورت میں دریافت
ہو چکا ہے اور ہم اس کا ایک فوٹو آگے چل کر درج کر رہے ہیں.اس خط میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہی عبارت يأهْلَ الْكِتبِ تَعَالَوْا إلى كَلِمَةِ...والی درج کرائی تھی.پس جب یہ بات
قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ عبارت مقوقس والے خط کا حصہ بھی تھی اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ مقوقس والا
خط اور ہرقل والا خط ایک ہی زمانہ میں لکھے گئے تو پھر بہر حال ان خطوں کی صداقت کا معاملہ تو کسی صورت
میں مشکوک نہیں سمجھا جا سکتا.وَهُوَ الْمُرَادُ.جو
تبلیغی خط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قل کے نام لکھا وہ اپنے معانی اور الفاظ کی خوبصورتی
اور جامعیت کے لحاظ سے ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی تحریر ہے.اس تحریر کے الفاظ کو بہت مختصر ہیں مگر اس
عبارت کا ایک ایک لفظ دلکش نگینوں کا حکم رکھتا ہے جو ایک اعلیٰ درجہ کے جڑاؤ زیور میں ایک باکمال ہنرمند
نصب کرتا ہے.حق یہ ہے کہ اس مختصر سے خط میں اسلام کی تبلیغ کا اور خصوصاً اس تبلیغ کا جو ایک مسیح کو
مخاطب کر کے ہونی چاہئے بہترین نمونہ درج کر دیا گیا ہے اور اس میں تو حید کا بھی وہ جامع سبق موجود
ہے جس کی نظیر نہیں ملتی.اور پھر اسلوب بیان ایسا لطیف ہے کہ گویا بشارت وانذار کی دو کامل نہریں
پہلو بہ پہلو رواں ہیں اور ایک طرف بلا وجہ دل دکھانے اور دوسری طرف مداہنت کے پردہ میں حق کو
چھپانے کے بغیر اسلامی صداقت کا مکمل نقشہ کھینچ دیا گیا ہے اور آخر میں اپنے اس فولادی عزم کا اظہار بھی
کر دیا گیا ہے کہ تم ما نویا نہ مانو ہم تو بہر حال اسلام کی خدمت کا بیڑا اٹھا چکے ہیں.اَللهُمَّ صَلَّى عَلَى
مُحَمَّدٍ وَبَارِک وَسَلِّمُ.ہرقل والے خط کے واقعہ سے یہ بھاری سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ سچی قربانی کی روح کے بغیر کوئی
بڑی صداقت قبول نہیں کی جاسکتی.ہرقل کے وہ سوالات جو اس نے ابوسفیان سے کئے اس بات کا ثبوت
ہیں کہ وہ ایک غیر معمولی عقل و دانش کا انسان تھا جس نے سلسلۂ رسالت اور سلسلہ ایمانیات کا کافی
گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا.پھر اس نے جس طرح اسلام کی صداقت سے متاثر ہوکر اپنے درباریوں کو اپنا ہم
خیال بنانے کی کوشش کی ، وہ نہ صرف اس کی حسن تدبیر بلکہ ایک حد تک اس کے جذبہ دینداری کی بھی دلیل
ہے.مگر پھر بھی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ ایمان کی نعمت سے محروم رہا اور بالآخر اسلام کی فوجوں سے لڑتا
ہوا اس جہان سے رخصت ہوا.اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس کی روح اس بھاری قربانی کے
زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۴۲
Page 926
۹۱۱
لئے تیار نہیں تھی جو کچی دینداری کے لئے ضروری ہے.وہ اپنی دنیا کی جاہ وعظمت کھونے کے بغیر اپنے
درباریوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا اسلام کی طرف قدم اٹھانا چاہتا تھا.وہ ایک حد تک دین کا طالب ضرور
تھا مگر دنیا کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا اور یہی کمزوری اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی.بیشک ابوبکر اور
عمر نے بھی دنیا کی بہترین نعمتوں اور عزتوں
کا ورثہ پایا مگر انہوں نے اسلام کے ساتھ سودا نہیں کرنا چاہا.وہ
خالی
ہاتھ ہو کر محض دین کی خاطر اسلام کی طرف آئے اور پھر خدا نے جو کسی کا قرضہ اپنے ذمہ نہیں رکھا کرتا
انہیں وہ سلطنت عطا کی جس کے سامنے قیصر و کسریٰ کی مجموعی سلطنت بھی ماند تھی.مگر قیصر خالی ہاتھ ہو کر
اسلام کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے ڈرا.اس نے اپنا کمزور ہاتھ اسلام کی طرف بڑھایا اور مضبوط ہاتھ اپنی
حکومت کے عصا پر جمائے رکھا.نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بٹے ہوئے دل کو نہ تو دین ہی ملا اور نہ ہی دنیا
زیادہ دیر تک اس کے ہاتھوں میں ٹھہر سکی.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نکتہ شناس تھا اور آپ کسی کی ذراسی نیکی کو بھی فراموش کرنا
نہیں جانتے تھے.چنانچہ روایت آتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ کسری نے
تو آپ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا ہے مگر قیصر نے گو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا لیکن بظاہر عزت اور ادب
سے پیش آیا ہے تو آپ نے فرمایا :
اَمَّا هَؤُلَاءِ فَيُمَزَّقُونَ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُونَ لَهُمْ بَقِيَّةٌ
یعنی ایرانی حکومت تو فوراً پاش پاش کر دی جائے گی مگر رومی حکومت کو خدا کچھ مہلت عطا کرے گا.“
سو بعینہ یہی ہوا کہ کسریٰ کی حکومت تو چند سال کے اندر خاک میں مل گئی مگر قیصر کی سلطنت بہت
ساحصہ چھینے جانے کے باوجود قسطنطنیہ اور اس کے گردونواح میں سینکڑوں سال تک قائم رہی.فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ -
سری کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آنحضرت صلی الہ علیہ وسلم کا دوسرا تلیفی خط
کسری شہنشاہ فارس کے نام تھا.جیسا کہ
او پر بتایا جا چکا ہے کسری فارس کے بادشاہوں کا سرکاری اور موروثی لقب تھا اور جس زمانہ کا اہم ذکر کر رہے
ہیں اس زمانہ میں فارس کے بادشاہ کا ذاتی نام خسرو پرویز بن ہرمز تھا جو اسیران کے مشہور ساسانی خاندان
سے تعلق رکھتا تھا.یہ بادشاہ جو بڑی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا مالک تھا مذ ہبا آتش پرست یعنی مشرک
کتاب الاموال بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۴۲
: خلافت اسلامیہ مصنفہ سرولیم میور
Page 927
۹۱۲
تھا اور یہی اس کی رعایا کا مذہب تھا جو اپنے بادشاہ کو بھی قابل پرستش خیال کرتی تھی.فارس کے کسری ایک
طرح سے عرب کے ملک پر بھی گویا اپنا سیاسی حق جماتے تھے.کیونکہ عرب کے علاقہ بحرین اور علاقہ یمن
کے رئیس دونوں کسری کے ماتحت تھے اور کسریٰ کی طرف سے ان علاقوں کے والی یعنی گورنر سمجھے جاتے
تھے.یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کی طرف تبلیغی خط لکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا
تو در باری آداب کے پیش نظر اپنا خط پہلے رئیس بحرین کی طرف بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ یہ خط
آگے کسری کے نام بھجوادے.اسی طرح جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے جب خسرو پرویز نے غصہ میں
آکر نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے احکام صادر کئے تو ان احکام کے اجراء کے لئے اس
نے اپنے یمن کے گورنر کو ہدایت بھجوائی.بہر حال بحرین اور یمن پر اقتدار حاصل ہونے کی وجہ سے کسری
کو عرب کے معاملات میں کافی دلچسپی تھی اور وہ عرب کی ہر نئی تحریک کو طبعا شک کی نظر سے دیکھتا تھا.عرب کے معاملات میں کسری کی دلچسپی کا دوسرا بڑا باعث عرب کے یہودی قبیلے تھے جو مدینہ اور
خیبر اور وادی القریٰ وغیرہ میں کثرت سے آباد تھے.یہ یہودی قبیلے طبعاً اور روایتاً قیصر کی عیسائی حکومت
کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ حق یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے سخت خلاف تھے اور دوسری طرف
قیصر کی حکومت یہودیوں کے متعلق معاندانہ رویہ رکھتی تھی اور ہر قل نے تو خصوصیت سے ان کے خلاف
تشدد کا دروازہ کھول رکھا تھا.اندریں حالات عرب کے ماحول میں صرف فارس کی حکومت ہی ایسی تھی
جس کے ساتھ عرب کے یہودی تعلقات رکھ سکتے تھے.یہ تعلقات یزدجر و اول کے عہد میں شروع
ہوئے جس کی ایک بیوی یہودی نسل کی تھی اور پھر خسرو پرویز کے زمانہ میں اپنے کمال
کو پہنچ گئے جبکہ
یہودیوں اور ایرانی حکومت کے درمیان گہرے تعلقات پیدا ہو چکے تھے.تعرب کے یہودی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کثرت کے ساتھ کسری کے دربار میں جاتے رہتے تھے اور جہاں تک ان کا
بس چلتا تھا خسرو پرویز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے تھے.اس حقیقت کوسر ولیم میور
نے بھی اشارہ تسلیم کیا ہے."
میدوہ زمانہ تھا جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے نام تبلیغی خط روانہ کیا.یہ خط آپ نے اپنے
ا بخاری کتاب العلم و کتاب الجہاد
ملاحظہ ہو ہسٹوریز ہسٹری آف دی ورلڈ جلدے صفحہ ۱۷۵.نیز دیکھو ہسٹری آف دی نیشنز، مصنفہ بچن سنز صفحه ۵۵۰
جیوالیش انسائیکلو پیڈیا جلد ۹ صفحه ۴۴۸ زیر عنوان پرشیا
: لائف آف محمد صفحه ۳۷۱
Page 928
۹۱۳
قدیم اور مخلص صحابی عبد اللہ بن حذافہ سہمی کے ہاتھ بھجوایا.اور انہیں ہدایت کی کہ آپ کے خط کو پہلے بحرین
کے رئیس کے پاس لے جائیں اور پھر اس کے توسط سے کسری تک پہنچیں تے اس رئیس بحرین کا نام
منذر بن ساوی تھا جو بحرین کے علاقہ میں کسریٰ کا نائب السلطنت تھا.یہ خط بھی قیصر کے خط کی طرح
با قاعدہ مہر لگا کر بھیجا گیا تھا اور اس کی عبارت یہ تھی :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلَ اللَّهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمٍ فَارِسَ -
سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَآمَنَ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَشَهِدَانُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - اَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ اللَّهِ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَى النَّاسِ
كَافَّةً لَانْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ - أَسْلِمُ تُسْلَمُ.فَإِنْ تَوَلَّيْتَ
فَعَلَيْكَ إِثْمَ الْمَجُوس
یعنی ” میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بے مانگے رحم کرنے والا اور اعمال کا
بہترین بدلہ دینے والا ہے.یہ خط خدا کے رسول محمد کی طرف سے فارس کے رئیس کسری کے نام
ہے.سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتا اور
اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے.اور وہ
اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے.اے رئیس فارس! میں
آپ کو خدا کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں سب انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا
ہوں تا کہ میں ہر زندہ انسان کو ہوشیار کر دوں اور تا انکار کرنے والوں پر خدا کا فیصلہ واجب ہو
جائے.اے رئیس فارس! آپ اسلام کو قبول کریں کیونکہ اب آپ کے لئے صرف اسی میں سلامتی
کا رستہ ہے لیکن اگر آپ روگردانی کریں گے تو یا درکھیں کہ اس صورت میں ( آپ کے اپنے
گناہ کے علاوہ ) آپ کی مجوس رعایا کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہو گا.“
عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ جب میں اس خط کے ساتھ کسری کے دربار میں پہنچا اور اجازت
ملنے کے بعد کسری کے سامنے اس خط کو پیش کیا تو اس نے یہ خط اپنے ایک ترجمان کے سپرد کیا کہ تا وہ
اسے پڑھ کر سنائے.جب ترجمان نے اس خط کو پڑھا تو کسری اس کے مضمون کوسن کر غصہ سے بھر گیا اور
زرقانی و تاریخ خمیس
۳: زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۴۱
بخاری کتاب العلم و کتاب الجہاد
تاریخ خمیس و زرقانی بروایت واقدی
Page 929
۹۱۴
،،
ترجمان کے ہاتھ سے خط لے کر اسے یہ کہتے ہوئے ریزہ ریزہ کر دیا کہ میرا غلام ہوکر مجھے اس طرح
مخاطب کرتا ہے! روایت آتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹی کی اس حرکت کی اطلاع پہنچی
تو آپ نے دینی غیرت کے جوش میں فرمایا ” خدا خود ان لوگوں کو پارہ پارہ کرے..اور ایک دوسری
روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اَمَا هَؤُلَاءِ فَيُمَزَّقُوْنَ یعنی ”اب
لوگ خود ریزہ ریزہ کر دئے جائیں گے.‘“.کسری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑنے پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ یہودی پرا پیگینڈا
کے گہرے تاثرات کے ماتحت اس نے اپنے یمن کے گورنر کو جس کا نام باذان تھا ہدایت فرمائی کہ حجاز
میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی طرف فوراً د وطاقتور آدمی بھجوا دو تا کہ وہ اسے گرفتار کر کے
ہمارے سامنے حاضر کریں اور ایک روایت یہ ہے کہ دو آدمی بھجوا کر اس سے تو بہ کراؤ اور اگر وہ انکار
کرے تو اسے قتل کر دیا جائے.چنانچہ باذان نے اس غرض کے لئے اپنے ایک قہرمان یعنی سیکرٹری کو جس
کا نام بانو یہ تھا منتخب کیا اور اس کے ساتھ ایک مضبوط سوار مقرر کر کے مدینہ کی طرف بھجوادیا اور ان کے
ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی بھجوایا کہ آپ فوراً ان لوگوں کے ساتھ کسری کی خدمت
میں حاضر ہو جائیں.جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باذان کا خط
دے کر بطریق نصیحت سمجھایا کہ بہتر ہے آپ ہمارے ساتھ چلے چلیں ورنہ کسری آپ کے ملک اور قوم کو
تباہ کر کے رکھ دے گا.آپ نے ان کی یہ بات سن کر تبسم فرمایا اور جواب میں اسلام کی تبلیغ کی اور پھر فرمایا
کہ تم آج رات ٹھہرو میں انشاء اللہ تمہیں کل جواب دوں گا.پھر جب وہ دوسرے دن آپ کے پاس
آئے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا.ابْلِغَا صَاحِبَكُمَا أَنَّ رَبِّي قَتَلَ رَبَّهُ فِى هَذِهِ اللَّيْلَةِ -
یعنی اپنے آقا ( والی یمن ) سے جا کر کہہ دو کہ میرے رب یعنی خدائے ذوالجلال نے
اس کے رب یعنی کسری“ کو آج رات قتل کر دیا ہے.“
چنانچہ بانو یہ اور اس کا ساتھی واپس لوٹ گئے اور باذان کے پاس جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
پیغام پہنچایا.باذان نے کہا جو بات یہ شخص کہتا ہے اگر وہ اسی طرح ہو جائے تو پھر وہ واقعی خدا کا نبی
ہوگا.چنانچہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ باذان کو خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ کا ایک خط پہنچا جس میں
ل : طبری و تاریخ خمیس و زرقانی : بخاری کتاب العلم و کتاب الجہاد ۳ : زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۳۲
Page 930
۹۱۵
لکھا تھا کہ ”میں نے ملکی مفاد کے ماتحت اپنے باپ خسرو پرویز کو جس کا رویہ ظالمانہ تھا اور جو اپنے ملک
کے شرفاء کو بے دریغ قتل کرتا جار ہا تھا قتل کر دیا ہے.پس جب تمہیں میرا یہ خط پہنچے تو میرے نام پر
اپنے علاقہ کے لوگوں سے اطاعت کا عہد لو.اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے تمہیں عرب کے
ایک شخص کے متعلق ایک حکم بھیجا تھا اسے اب منسوخ سمجھو اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو.“ جب
باذان کو نئے کسری شیرویہ بن خسرو کا یہ فرمان پہنچا تو اس نے بے اختیار ہو کر کہا کہ پھر تو محمد ( صلی اللہ
علیہ وسلم ) کی بات سچی نکلی.معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کے برحق رسول ہیں اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں.چنانچہ اس نے اسی وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کا خط لکھ دیا اور اس کے ساتھ یمن
کے کئی اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے.اور روایت آتی ہے کہ خسرو پرویز اسی رات قتل ہوا تھا جس رات
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق خدا سے اطلاع پائی تھی.یہ ایک عجیب بات ہے کہ قیصر و کسریٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کے ساتھ جو جو
سلوک کیا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے معاملہ کیا.چنانچہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
خط پھاڑ کر پھینک دینے کی وجہ سے کسری کی بھاری سلطنت چند سال کے اندر ریزہ ریزہ کر دی گئی وہاں
قیصر کی طرف سے آپ کے خط کے ساتھ مؤدبانہ رویہ رکھنے پر خدا تعالیٰ نے اس کی نسل کو کافی لمبی مہلت
دی اور اس کے خاندان نے سینکڑوں سال حکومت کی.چنانچہ روایت آتی ہے کہ جب قیصر کا ایک تنوخی
سفیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے اسے یہ الفاظ فرمائے کہ :
میں نے کسری کو ایک خط لکھا مگر اس نے اسے پھاڑ دیا.اس کی وجہ سے میں یقین رکھتا
ہوں کہ خدا اسے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور اس کی سلطنت جلد تباہ ہوکر رہے گی مگر اس کے
مقابل پر میں نے ایک خط تمہارے آقا قیصر کو بھی لکھا اور اس نے اس کے متعلق ادب کا رویہ
اختیار کیا اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا.میں امید کرتا ہوں کہ جب تک ان میں نیکی کا مادہ ہے
خدا اس کے خاندان کی کچھ نہ کچھ طاقت ضرور قائم رکھے گا.“
تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ بعینہ یہی ان دونوں حکومتوں کے ساتھ خدا کا سلوک ہوا بلکہ جیسا کہ
ہم آگے چل کر دیکھیں گے ان دو خطوں کے علاوہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو تبلیغی خطوط ان
ایام میں لکھے اور ان خطوں کے پہنچنے پر مکتوب الیہم نے جو جو رویہ اختیار کیا اسی کے مطابق خدائے حکیم وقدیر
طبری جلد ۳ صفحه ۱۵۷۲ تا صفحه ۵۷۴ او تاریخ خمیس
زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۴۲
Page 931
۹۱۶
نے ان کے ساتھ سلوک کیا.اور اگر غور کیا جائے تو یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک
بھاری دلیل ہے.کسری والے خط کے متعلق یہ بات بھی یادرکھنی چاہئے کہ جہاں قدیم مؤرخین نے صراحت کے
ساتھ لکھا ہے کہ خسرو پرویز نے جو حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یمن کے والی کے نام جاری کیا تھا
اس کا سبب وہ خط تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھجوایا وہاں بعض جدید محققین نے یہ بات ثابت
کرنے کی کوشش کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لکھنے کا واقعہ بعد کا ہے اور خسرو پرویز کا حکم
یہودی پرا پیگنڈے کی وجہ سے اس سے پہلے جاری ہو چکا تھا.دوسرا اختلاف یہ ہے کہ آیا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا تبلیغی خط خسرو پرویز کے نام لکھا گیا تھا یا اس کے بیٹے شیرویہ کے نام؟ میں نے اس جگہ معروف
خیال کی اتباع کی ہے یعنی یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط خسرو پرویز کے نام تھا اور اس نے آپ کے
خلاف احکام جاری کئے تھے.واللہ اعلم بالصواب.دراصل میرے پاس اس وقت لاہور میں ان کتابوں کا
پورا ذخیرہ موجود نہیں ہے جن کا مطالعہ اس قسم کے سوال کی کامل تحقیق کے لئے ضروری ہے.اس لئے
فی الحال معروف خیال درج کر دیا گیا ہے اور یہ اختلاف بھی ایسا نہیں ہے کہ جو زیادہ اہمیت رکھتا ہو.اگر خدا نے چاہا تو بصورت ضرورت بعد میں اصلاح کی جاسکے گی.مقوقس مصر کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا اخط
bi
مقوقس والی مصر کے نام تھا جو قیصر
کے ماتحت مصر اور اسکندریہ کا والی یعنی موروثی حاکم تھا اور قیصر کی طرح مسیحی مذہب کا پیر تھا.اس کا ذاتی
نام جریج بن مینا تھا اور وہ اور اس کی رعایا قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے.یہ خط آپ نے اپنے ایک بدری
صحابی حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ بھجوایا اور اس خط کے الفاظ یہ تھے.بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الْمَقَوْقَسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ.سَلامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى اَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمُ تُسْلَمُ يُؤْتِكَ اللَّهُ
أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ.فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْقِبْطِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ الَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
زرقانی و مواہب اللد نیه
Page 932
۹۱۷
یعنی ” میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بے مانگے رحم کرنے والا اور اعمال
کا بہترین بدلہ دینے والا ہے.یہ خط محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے قبطیوں
کے رئیس مقوقس کے نام ہے.سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اس کے بعد
اے والیمصر ! میں آپ کو اسلام کی ہدایت کی طرف بلاتا ہوں.مسلمان ہو کر خدا کی سلامتی
کو قبول کیجئے کہ اب صرف یہی نجات کا رستہ ہے.اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دے گا لیکن
اگر آپ نے روگردانی کی تو (علاوہ خود آپ کے اپنے گناہ کے ) قبطیوں کا گناہ بھی آپ کی
گردن پر ہوگا اور اے اہل کتاب اس کلمہ کی طرف تو آجاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان
مشترک ہے یعنی ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک
نہ ٹھہرائیں اور خدا کو چھوڑ کر اپنے میں سے ہی کسی کو اپنا آقا اور حاجت روا نہ گردانیں پھر اگر
ان لوگوں نے روگردانی کی تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو بہر حال خدائے واحد کے
فرمانبردار بندے ہیں.جب حاطب بن ابی بلتعہ اسکندریہ میں پہنچے تو مقوقس کے حاجب یعنی در بان سے مل کر اس کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا.مقوقس نے خط پڑھا اور پھر حاطب بن ابی بلتعہ
سے مخاطب ہو کر نیم مذاقیہ رنگ میں کہا کہ اگر تمہارا یہ صاحب واقعی خدا کا نبی ہے تو ( اس خط کے بھجوانے کی
بجائے ) اس نے میرے خلاف خدا سے یہ دعا ہی کیوں نہ کی کہ خدا اسے مجھ پر مسلط کر دے.حاطب
نے جواب دیا کہ اگر یہ اعتراض درست ہے تو وہ حضرت عیسی پر بھی پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفوں
کے خلاف اس قسم کی دعا کیوں نہیں کی.پھر حاطب نے مقوقس کو از راہ نصیحت کہا کہ آپ ( سنجیدگی کے
ساتھ ) غور فرمائیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کے اسی ملک مصر میں ایک ایسا شخص ( فرعون ) گزر چکا ہے جو
یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہی ساری دنیا کا رب اور حاکم اعلیٰ ہے.جس پر خدا نے اسے ایسا پکڑا کہ وہ اگلوں
اور پچھلوں کے لئے عبرت بن گیا.پس میں آپ سے مخلصانہ طور پر عرض کروں گا کہ آپ دوسروں کے
حالات سے عبرت پکڑیں اور ایسے نہ نہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے حالات سے عبرت پکڑیں.مقوقس
نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے ایک دین حاصل ہے اس لئے جب تک ہمیں اس سے کوئی بہتر دین نہ
ملے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے.حاطب نے جواب دیا کہ اسلام وہ دین ہے جو سب دوسرے دینوں سے غنی
کر دیتا ہے لیکن وہ یقیناً آپ کو اس بات سے نہیں روکتا کہ آپ حضرت مسیح ناصری پر بھی ایمان لائیں بلکہ
Page 933
۹۱۸
وہ سب بچے نبیوں پر ایمان لانے کی تلقین کرتا ہے.اور جس طرح حضرت موسی نے حضرت عیسی کی
بشارت دی تھی اسی طرح حضرت عیسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی ہے.اس پر
مقوقس کچھ سوچ میں پڑ کر خاموش ہو گیا مگر اس کے بعد ایک دوسری مجلس میں جبکہ بعض بڑے بڑے پادری
بھی موجود تھے مقوقس نے حاطب سے پھر کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی اپنے وطن سے نکالے گئے تھے
انہوں نے اس موقع پر اپنے نکالنے والوں کے خلاف بددعا کیوں نہ کی تاکہ وہ ہلاک کر دئے جاتے؟
حاطب نے جواب دیا کہ ہمارے نبی تو صرف وطن سے نکلنے پر مجبور ہوئے مگر آپ کے مسیح کو تو یہودیوں
نے پکڑ کر سولی کے ذریعہ ختم ہی کر دینا چاہا مگر پھر بھی وہ اپنے مخالفوں کے خلاف بددعا کر کے انہیں ہلاک
نہ کر سکے.مقوقس نے متاثر ہو کر کہا تم بیشک ایک دانا انسان ہو اور ایک دانا انسان کی طرف سے سفیر
بن کر آئے ہو.اس کے بعد کہنے لگا.میں نے تمہارے نبی کے معاملہ میں غور کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ
انہوں نے واقعی کسی بری بات کی تعلیم نہیں دی اور نہ کسی اچھی بات سے روکا ہے.پھر اس نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایک ہاتھی دانت کی ڈبیہ میں رکھ کر اس پر اپنی مہر لگائی اور اسے حفاظت کے لئے اپنے
گھر کی ایک معتبر لڑکی کے سپر د کر دیا.اس کے بعد مقوقس نے اپنے ایک عربی دان کا تب کو بلایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام
مندرجہ ذیل خط املاء کرا کے حاطب کے حوالہ کیا.اس خط کی عبارت یہ تھی :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْمَقَوْقَسِ عَظِيمِ الْقِبْطِ.سَلَامٌ
عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَرَأَتُ كِتَابَكَ وَفَهِمْتُ مَاذَكَرْتَ فِيهِ وَمَا تَدْعُوُالَيْهِ - وَقَدْ عَلِمُتُ
أَنَّ نَبِيَّا قَدْ بَقِيَ وَكُنْتُ أَظُنُّ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الشَّامِ - وَقَدْ أَكْرَمُتُ رَسُولَكَ وَبَعَثْتُهُ
إِلَيْكَ بِجَارِيَتَيْنِ لَهُمَامَكَانَ مِنَ الْقِبْطِ عَظِيمٌ وَكِسْوَةٌ وَأَهْدَيْتُ إِلَيْكَ بَغُلَةٌ
لِتَرُكُبَهَا وَالسَّلَامُ -
یعنی ” خدا کے نام کے ساتھ جو رحمن اور رحیم ہے.یہ خط محمد بن عبد اللہ کے نام قبطیوں کے
رئیس مقوقس کی طرف سے ہے.آپ پر سلامتی ہو.میں نے آپ کا خط اور آپ کے مفہوم کو سمجھا
اور آپ کی دعوت پر غور کیا.میں یہ ضرور جانتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے مگر میں خیال
کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں پیدا ہوگا (نہ کہ عرب میں ) اور میں آپ کے سفیر کے ساتھ عزت
زرقانی و تاریخ خمیس
Page 934
۹۱۹
سے پیش آیا ہوں اور میں اس کے ساتھ دولڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ
حاصل ہے اور میں کچھ پار چات بھی بھجوا رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لئے ایک خچر بھی
بھجوا رہا ہوں.والسلام 1
اس خط سے ظاہر ہے کہ مقوقس مصر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اینچی کے ساتھ عزت سے پیش آیا
اور اس نے آپ کے دعوئی میں ایک حد تک دلچسپی بھی لی مگر بہر حال اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور
دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ عیسائی مذہب پر ہی اس کی وفات ہوئی.اس کی گفتگو کے انداز سے
یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ بے شک مذہبی امور میں دلچسپی تو لیتا تھا مگر جو سنجیدگی اس معاملہ میں ضروری ہے
وہ اسے حاصل نہیں
تھی.اس لئے اس نے بظاہر مؤدبانہ رنگ رکھتے ہوئے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت کو ٹال دیا.جو دولڑکیاں مقوقس نے بھجوائی تھیں ان میں سے ایک کا نام ماریہ اور دوسری کا نام سیرین تھا.اور یہ
دونوں آپس میں بہنیں تھیں اور جیسا کہ مقوقس نے اپنے خط میں لکھا تھا وہ قبطی قوم میں سے تھیں اور یہ
وہی قوم ہے جس سے خود مقوقس کا تعلق تھا اور یہ لڑکیاں عام لوگوں میں سے نہیں تھیں بلکہ مقوقس کی اپنے
تحریر کے مطابق ”انہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل تھا.در اصل معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں میں یہ پرانا
دستور تھا کہ اپنے ایسے معزز مہمانوں کو جن کے ساتھ وہ تعلقات کو بڑھانا چاہتے تھے رشتہ کے لئے اپنے
خاندان یا اپنی قوم کی شریف لڑکیاں پیش کر دیتے تھے.چنانچہ جب حضرت ابرا ہیم مصر میں تشریف لے
گئے تو مصر کے رئیس نے انہیں بھی ایک شریف لڑکی (حضرت ہاجرہ ) رشتہ کے لئے پیش کی تھی جو بعد میں
حضرت اسماعیل اور ان کے ذریعہ بہت سے عرب قبیلوں کی ماں بنی..بہر حال مقوقس کی بھجوائی ہوئی
لڑکیوں کے مدینہ پہنچنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو تو خود اپنے عقد میں لے لیا اور ان کی
بہن سیرین کو عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت کے عقد میں دے دیا ہے یہ ماریہ وہی مبارک خاتون
ہیں جن کے بطن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے.جو زمانہ نبوت
ے معلوم ہوتا ہے کہ مقوقس نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی نقل میں بسم اللہ کے الفاظ لکھ دئے ہوں گے ورنہ
ان میں اس کا رواج نہیں تھا
۳: کتاب هذا حصہ اول
تاریخ خمیس
: زرقانی جلد ۳ حالات ماریہ قبطیہ واسدالغابہ حالات ماریه وسیرین
۵: اسدالغابه
Page 935
۹۲۰
کی گویا واحد اولا د تھی.یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حاطب بن
ابی بلتعہ کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئی تھیں.جو خچر اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں آئی وہ
سفید رنگ کی تھی اور اس کا نام دلدل تھا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اکثر سواری فرمایا کرتے تھے اور
غزوہ حنین میں بھی یہی خچر آپ کے نیچے تھی.یہ سوال کہ آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کوز وجہ کے طور پر اپنے عقد میں لیا یا کہ
صرف ملک یمین کے رنگ میں اپنے عقد میں رکھا ایک اختلافی سوال ہے جس کی تفصیل میں ہمیں اس جگہ
جانے کی ضرورت نہیں.بہر حال دوباتیں قطعی طور پر یقینی ہیں.ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ماریہ کو شروع سے ہی پردہ کرایا ہے اور پردہ کے متعلق ثابت ہے کہ وہ صرف آزاد عورتیں اور ازواج
ہی کرتی تھیں.چنانچہ روایت آتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد ایک
یہودی رئیس کی بیٹی صفیہ کے ساتھ عقد کیا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ
ہیں یا کہ محض ملک یمین.پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ کرایا تو صحابہ نے سمجھ لیا کہ
وہ زوجہ ہیں نہ کہ ملک یمین.دوسرے یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے کبھی کوئی ذاتی غلام نہیں رکھا بلکہ جو لونڈی یا غلام بھی آپ کے قبضہ میں آیا آپ نے اسے آزاد
کر دیا.اس لحاظ سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ماریہ قبطیہ کو لونڈی کے طور پر اپنے پاس
رکھنا بعید از قیاس اور نا قابل قبول ہے.واللہ اعلم.ویسے اگر لونڈیوں کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ
ملاحظہ کرنا ہو تو کتاب ھذا کے حصہ دوم کے صفحات ۴۷۲ تا ۴۷۸ مطالعہ کئے جائیں.مقوقس والے خط کے متعلق ایک خاص بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ وہ کئی سو سال پر دہ خفا میں مستور
رہنے کے بعد قریباً ایک سو سال ہوا کہ اپنی اصلی صورت میں دریافت ہو چکا ہے اور ہم اس جگہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متبرک خط کا فوٹو یعنی عکس درج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں.رسم خط
میں کافی تبدیلی ہو جانے کے باوجود اس عکس کے اکثر الفاظ نظر غور کے ساتھ پڑھے جاسکتے ہیں اور وہ
: زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۷۲
ابن سعد بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۷۲
بخاری بحوالہ زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۵۶ ، ۲۵۷
۵ کتاب ھذا حصہ دوم
: تاریخ الخمیس
Page 936
۹۲۱
بعینہ وہی الفاظ ہیں جو ہم نے اسلامی کتب کے حوالہ سے اوپر درج کئے ہیں.یہ خط ۱۸۵۸ء میں بعض
فرانسیسی سیاحوں کو مصر کی ایک خانقاہ میں ملا اور اب اصل خط قسطنطنیہ میں موجود ہے.اور اس کا فوٹو بھی
شائع ہو چکا ہے.اس خط کا دریافت کرنے والا مسیو استین بر تیمی تھا اور غالبا سب سے پہلے اس کا فوٹو
مصر کے مشہور جریدہ الہلال بابت نومبر ۱۹۰۴ء میں شائع ہوا تھا اور پھر پروفیسر مارگولیتھ نے بھی اپنی کتاب
محمد اینڈ دی رائز آف اسلام میں اسے شائع کیا.اسی طرح وہ مصر کی ایک جدید تصنیف تاریخ الاسلام
ایساسی مصنفہ الدكتور حسن بن ابراہیم استاذ التاریخ الاسلامی جامعہ مصریہ " میں بھی چھپ چکا ہے اور بہت
سے غیر مسلم محققین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ وہی اصل خط ہے جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے
مقوقس مصر کو لکھا تھا.ضمناً اس خط کی دریافت جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حدیث اور تاریخ اسلامی کی روایت
کے عین مطابق ہے اس بات کا بھاری ثبوت مہیا کرتی ہے کہ معتبر جامعین حدیث اور محقق مؤرخین اسلام
نے روایات کے جمع کرنے میں کتنی بھاری احتیاط اور کتنی عظیم الشان امانت و دیانت سے کام لیا ہے.انہوں نے زبانی حافظہ کی بنا پر روایوں کے ایک لمبے سلسلہ کے ساتھ اس خط کی عبارت بیان کی اور بتایا کہ
فلاں موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان الفاظ کی تحریر مقوقس کو لکھی تھی اور پھر تیرہ سوسال کے
طویل زمانہ کے بعد اصل خط کے دریافت ہونے پر یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہوگئی کہ جو روایت
ان مسلمان محد ثین اور مؤرخین نے بیان کی تھی وہ حرف بحرف درست تھی.اس سے بڑھ کر اسلامی
روایات کی صحت اور محدثین کی دیانت وامانت کا کیا ثبوت ہوگا ؟ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب راوی
ہر لحاظ سے قابل اعتماد ہیں کیونکہ یقیناً ان میں حافظہ یا سمجھ یا دیانت کے لحاظ سے بعض کمزور راوی بھی
پائے جاتے تھے لیکن جو اچھے تھے ان کا تاریخ عالم میں جواب نہیں.( نوٹ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا عکس اگلے صفحہ پر ملاحظہ کریں.)
ل ریویو آف ریچز قادیان بابت ماہ اگست ۱۹۰۶
: صفحه ۳۶۴
: صفحہ ۱۹۸
Page 937
سم الله الرحم
الى
سو
ປ
تالم و سر
نم
العدي
وک
كان
"
لمكر
و
لح
x
تو لو حمو لوحات
۹۲۲
الله
الميط ساد
حطيم
سد
سلم ما سلم
هر علم
تمكيليا ليش..ل دلمه
+
الا الله
لا
للاد
مضا
حمله ماار
k
مس
;
بسم اله الخر الرحيم
من محمد عبد الله وَرَسُوله إلى المقوقي عَظِيمُ الْقِبْطِ سلام من
من اتبع الهدى أمَّا بعدُ فَانِي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَن تنام
يُؤْتِيكَ اللهُ أَجْرَكَ مَتَرتَينِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ كُلِ الْقِبْطِ وَمَجمعُ القِبْطِ
يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبتكر الأمية
إلا الله وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا يانا مسلمون
مُحمد رسول الله
Page 938
۹۲۳
نجاشی کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط کتاب ہذا کے حصہ اول میں براعظم
افریقہ کی عیسائی حکومت حبشہ کا ذکر کیا
جاچکا ہے.اس حکومت کے بادشاہ کا موروثی لقب نجاشی ہوا کرتا تھا.یہ بات بھی کتاب کے حصہ اول میں
گزر چکی ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں کے خلاف قریش کے مظالم نے زور پکڑا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنے بہت سے صحابہ کو (جن میں بعض عورتیں بھی شامل تھیں ) حبشہ بھجوا دیا تھا.اور با وجود قریش کے
پیچھا کرنے اور نجاشی کو طرح طرح سے بہکانے کے نجاشی حق وانصاف کے رستہ پر قائم رہا اور مسلمان
مہاجر ایک لمبے عرصہ تک اس کی حکومت میں امن و عافیت کے ساتھ رہتے رہے یہ نجاشی جس کا نام اصحمہ
تھا شروع سے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مداح تھا اور آپ کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتا تھا اور
آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی اس کا سلوک صرف منصفانہ ہی نہیں تھا بلکہ حقیقتامر بیا نہ تھا لیکن بہر حال وہ
ابھی تک عمومی رنگ میں خوش عقیدہ ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہوا تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط لکھے تو اس موقع پر ایک خط اپنے صحابی
عمرو بن امیہ ضمری کے ہاتھ نجاشی کے نام بھی لکھ کر بھجوایا.اس خط کی عبارت یہ تھی.بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى النَّجَاشِي مَلِكِ الْحَبْشَةِ سَلّمْ
أَنْتَ.أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ.وَاَشْهَدُ اَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْبَتُولِ وَإِنِّى اَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْمَوَالَاةِ عَلَى طَاعَتِهِ وَإِنْ تَتَّبِعُنِى وَتُؤْمِنُ بِالَّذِي جَاءَ نِي فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
وإِنِّي اَدْعُوكَ وَجُنُودَكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ فَاقْبِلُوا نَصِيْحَتِي وَقَدْ بَعَثْتُ
إِلَيْكَ ابْنَ عَمِّى جَعْفَراً وَمَعَهُ نَفَرْمِنَ الْمُسْلِمِينَ.وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
یعنی ” میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم
کرنے والا ہے.یہ خط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام ہے.اے بادشاہ! آپ پر خدا کی سلامتی ہو.اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس خدا کی حمد بیان کرتا
ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں.وہی زمین و آسمان کا حقیقی بادشاہ ہے جو تمام
خوبیوں کا جامع اور تمام نقصوں سے پاک ہے.وہ مخلوق کو امن دینے والا اور دنیا کی حفاظت
کتاب طذ ا حصہ اوّل صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۴
ابن سعد وزرقانی جلد ۳ صفحه ۳۴۴،۳۴۳
Page 939
۹۲۴
کرنے والا ہے اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ عیسی ابن مریم خدا کے کلام کے ذریعہ
مبعوث ہوئے اور اس کے حکم سے عالم وجود میں آئے جو اس نے مریم بتول پر نازل کیا
تھا.اوراے بادشاہ! میں آپ کو خدائے واحد کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں
اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کی اطاعت میں میرے ساتھ تعاون کریں اور میری اتباع
اختیار کرتے ہوئے اس کلام پر ایمان لائیں جو مجھ پر نازل ہوا ہے کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں
اور اسی حیثیت میں آپ کو اور آپ کی رعایا کو خدا کی طرف بلاتا ہوں.میں نے آپ کو اپنا پیغام
پہنچا دیا ہے اوراخلاص اور ہمدردی کے ساتھ آپ کو صداقت کی طرف دعوت دی ہے.پس
میرے اس اخلاص اور ہمدردی کو قبول کریں.میں (اس سے قبل ) آپ کی طرف اپنے چچازاد
بھائی جعفر اور ان کے ساتھ بعض دوسرے مسلمانوں کو بھجوا چکا ہوں.اور سلامتی ہو ہر اس شخص پر
جوخدا کی ہدایت کو اختیار کرتا ہے.“
جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط نجاشی کو پہنچا تو اس نے اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور ادب
کے طریق پر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول
ہیں یا پھر اس نے ایک ہاتھی دانت کی ڈبیہ منگوائی اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط محفوظ کر کے
رکھ دیا اور کہا میں یقین کرتا ہوں کہ جب تک یہ خط ہمارے گھرانے میں محفوظ رہے گا ، اہل حبشہ اس کی وجہ
سے خیرا اور برکت پاتے رہیں گے یہ تاریخ انمیس کا مصنف لکھتا ہے کہ یہ خط آج تک حبشہ کے شاہی
خاندان میں محفوظ ہے.اس کے بعد نجاشی نے ذیل کا جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا؟
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ النَّجَاشِي أَصْحَمَةِ سَلَامٌ
عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي هَدَانِي
لِلإِسْلَام أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِيُّ كِتَابُكَ يَارَسُولَ اللهِ فَمَا ذَكَرُتَ مِنْ أَمْرِعِيُسَىٰ فَوَرَبِّ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَزِيدُ مَا ذَكَرْتَ ثَفُرُوْقًا وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بَعَثْتَ بِهِ
إِلَيْنَا.فَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولَ اللهِ صَادِقًا مَصْدُوقًا وَقَدْ بَايَعْتُكَ وَبَايَعُتُ ابْنَ عَمِكَ
ابن سعد وزرقانی جلد ۳ صفحه ۳۶۶
تاریخ الخمیس جلد ۲ صفحه ۳۳ ۳۴ وزرقانی جلد ۳ صفحه ۳۶۶
Page 940
۹۲۵
وَأَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.....وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ لا
یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمن اور رحیم ہے.یہ خط محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )
کے نام نجاشی اصحمہ کی طرف سے ہے.یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو اور اس خدا کی طرف سے
برکتیں نازل ہوں جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں.اور وہی ہے جس نے مجھے اسلام کی
طرف ہدایت دی ہے اس کے بعد یا رسول اللہ آپ کا خط مجھے پہنچا.خدا کی قسم جو کچھ آپ نے
عیسی علیہ السلام کے متعلق بیان کیا ہے میں انہیں اس سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں سمجھتا.اور ہم
نے آپ کی دعوت حق کو سمجھ لیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے بچے رسول ہیں جن
کے متعلق پہلے صحیفوں میں بھی خبر دی گئی تھی.پس میں آپ کے چچا زاد بھائی جعفر کے ذریعہ آپ
کے ہاتھ پر خدا کی خاطر بیعت کرتا ہوں...اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر اور اس کی رحمتیں
اور برکتیں نازل ہوں.“
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط نجاشی کو لکھا اور نجاشی نے اس کا جو جواب دیا ان دونوں میں
ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے جو اوپر کے کسی اور خط میں نظر نہیں آتی.یعنی ایک طرف آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے خط کے الفاظ اس امید سے معمور نظر آتے ہیں کہ انشاء اللہ آپ کی تبلیغ سے نجاشی ضرور مسلمان
ہو جائے گا اور دوسری طرف نجاشی کا خط اس حقیقت کا حامل ہے کہ گویا اس کی روح پہلے سے صداقت کے
قبول کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہے.بہر حال خدا تعالیٰ نے نجاشی کو اسلام کی توفیق عطا کی.اور یہ وہی
نجاشی ہے جو ۹ ہجری میں فوت ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرماتے ہوئے اس کی
نماز جنازہ ادا کی کہ تمہارا ایک صالح بھائی نجاشی حبشہ میں فوت ہو گیا ہے.آؤ ہم سب مل کر اس کی
روح کے لئے دعا کریں ہے
جو نجاشی اس نجاشی کی وفات کے بعد حبشہ کے تخت پر بیٹھا اس کا نام روایات میں محفوظ نہیں ہے
مگر تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ایک تبلیغی خط لکھا تھا.مگر بدقسمتی سے
اس نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور مسیحی مذہب پر ہی فوت ہوا.کے غالباً یہی وجہ ہے کہ حبشہ میں
اسلام زیادہ پھیل نہیں سکا.بخاری و مسلم نیز زرقانی
: صحیح مسلم
زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۴۶ نیز صفحه ۳۶۶
Page 941
۹۲۶
اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ چونکہ یکے بعد دیگرے دونجاشیوں کو تبلیغی خط لکھے گئے
تھے.یعنی ایک خط تو اصحمہ نامی نجاشی کو لکھا گیا جس کے پاس ابتدائی صحابہ پناہ لینے کی غرض سے ہجرت
کر کے گئے تھے اور جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اسلام قبول کیا اور اسلام پر ہی ۹ ہجری
میں وفات پائی.اور دوسرا خط اس کے بعد آنے والے نجاشی کولکھا گیا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعوت کو قبول نہیں کیا.اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا.اس لئے بعض مؤرخین کو اس معاملہ میں غلطی
لگ گئی ہے اور انہوں نے دونوں نجاشیوں کو ایک ہی سمجھ لیا ہے.حالانکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ زمانوں میں دو علیحدہ نجاشیوں کو خط لکھے تھے.چنانچہ صحیح مسلم
میں حضرت انس کی صریح روایت آتی ہے کہ جس نجاشی کو بعد والا خط لکھا گیا وہ اس نجاشی کے علاوہ تھا جس
کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی.اور زرقانی اور تاریخ خمیس نے بھی اس معاملہ میں
مفصل بحث کر کے دونوں کو علیحدہ علیحدہ ثابت کیا ہے.یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نجاشی کو تبلیغی خط ارسال کیا جس
پر وہ مسلمان ہو گیا تو اسی وقت آپ نے اس کے نام ایک دوسرا خط پرائیویٹ مضمون کا بھی لکھا تھا.اس خط
میں آپ نے نجاشی کو دوباتوں کی طرف توجہ دلائی تھی.ایک یہ کہ وہ ابوسفیان کی بیٹی ام حبیبہ کے ساتھ آپ
کا غائبانہ نکاح پڑھ دے اور دوسرے یہ کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کو جنہیں حبشہ
میں گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا اپنے انتظام میں عرب واپس بھجوا دے.نجاشی نے ان دونوں باتوں کی
تعمیل کی یعنی اولاً اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُم حبیبہ کے نکاح کا اعلان کیا اور پھر حضرت
جعفر اور ان کے ساتھیوں کے لئے کشتی کا انتظام کر کے انہیں عرب میں واپس بھجوا دیا.یہ وہ زمانہ تھا جب
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے واپس آرہے تھے اور روایت آتی ہے کہ آپ حضرت جعفر
سے مل کر اتنے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا کہ
جعفر اور اس کے ساتھیوں کی آمد سے زیادہ خوشی ہوئی ہے.مگر افسوس ہے کہ حضرت جعفر کی زندگی نے
زیادہ وفا نہیں کی اور وہ اس کے تھوڑا عرصہ بعد ہی غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے.کے
ل : زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۴۶ نیز صفحه ۳۶۶ و تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۳۳ ۳۴۷
: حضرت علی کے بڑے بھائی
بخاری حالات غزوہ موتہ واسدالغابه وطبری وزرقانی
Page 942
۹۲۷
ام حبیبہ جن کی اس موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی وہ مکہ کے رئیس اعظم
ابوسفیان بن حرب کی بیٹی اور امیر معاویہ کی بہن تھیں.وہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں اور ان کے
خاوند عبیداللہ بن جحش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے جو حبشہ میں ہی وفات
پاگئے.ان کی وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب خیال کیا کہ اُم حبیبہ کو اپنے عقد میں
لے لیں.جس میں غالباً یہ دوہری غرض تھی کہ ایک تو اس طرح شاید ابوسفیان کو اسلام کی طرف مائل کیا
جا سکے اور دوسرے تا ام حبیبہ کی جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی کی بیوہ تھیں دلداری ہو جائے.ام حبیبہ جن کا
نام رملہ تھا ۴۴ ہجری میں فوت ہوئیں.نکاح پڑھنے سے پہلے نجاشی نے ام حبیبہ کو پیغام بھیج کر ان کی
باقاعدہ اجازت لی اور پھر ان کی طرف سے ان کے ایک قریبی عزیز خالد بن سعید نے ولی بن کر چارسو
دینار پر نکاح منظور کیا.اگر اس موقع پر اسلام کے مسئلہ تعداد از دواج پر بحث دیکھنی ہو تو کتاب هذا
حصہ دوم صفحہ ۴۸۹ تا ۵۰۴ ملاحظہ کئے جائیں.گودوسرے نجاشی نے جو غالباً 9 ہجری میں تخت نشین ہوا اسلام قبول نہیں کیا لیکن چونکہ پہلا نجاشی
مسلمان ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک لمبے عرصہ تک حبشہ میں پناہ لے کر امن
و عافیت کی زندگی پائی تھی اس لئے مسلمانوں نے اس ملک کے احسان
کا یہ بدلہ دیا کہ جہاں دنیا کے چاروں
کونوں میں ان کی فاتحانہ یلغار نے اسلام کی حکومت کا جھنڈا گاڑا وہاں انہوں نے حبشہ کے خلاف کبھی
فوج کشی نہیں کی.ان کی تلوار شمال میں بھی چلی اور جنوب میں بھی چلی اور پھر مشرق میں بھی چلی اور مغرب
میں بھی چلی اور چین اور راس کماری کی حد سے لے کر مراکش اور سپین کے آخری کناروں تک مسلمانوں
کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے روئے زمین کو ہلا دیا اور قیصر و کسریٰ جیسے عظیم الشان بادشاہ ان کے سامنے ریت
کے تو دوں کی طرح گر کر پیوست خاک ہو گئے مگر فتح کے اس عالمگیر سیلاب میں بھی اگر مسلمانوں کی تلوار کسی
ملک کے خلاف نہیں اٹھی تو وہ یہی حبشہ کی چھوٹی سی ریاست تھی.اس کے چاروں طرف کا علاقہ مسلمانوں
کے ماتحت آچکا تھا مگر جب وہ حبشہ کے قریب پہنچتے تھے تو ہمیشہ کتر کر ادھر ادھر سے گزر جاتے رہے اور اس
کے خلاف کبھی انگلی تک نہیں اٹھائی.اس کی تہ میں یہی اعلیٰ اخلاقی جذبہ کام کر رہا تھا کہ وہ اپنی انتہائی فتح
کے زمانہ میں سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی اس چھوٹے سے احسان
کو نہیں بھولنا چاہتے تھے جو حبشہ
کے نجاشی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابیوں کو پناہ دے کر ابتدائی مسلمانوں پر کیا تھا.یہ ایک
ل : ابن سعد وزرقانی واسد الغابه
Page 943
۹۲۸
بہت بھاری اخلاقی نکتہ ہے جس سے دنیا کی قومیں سبق حاصل کر سکتی ہیں.رئیس غسان کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پانچواں تبلیغی خط ریاست غنستان
کے فرمانروا حارث بن ابی شہر کے
نام لکھا گیا.یہ وہی حارث ہے جس کا ذکر قیصر والے خط کے تعلق میں بھی آچکا ہے.غسان کی ریاست
عرب کے ساتھ متصل جانب شمال واقع تھی اور اس کا رئیس قیصر کے ماتحت ہوا کرتا تھا.آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے یہ خط اپنے صحابی شجاع بن وہب کے ہاتھ روانہ فرمایا اور آپ نے اپنے اس خط میں حارث
کو اسلام کی دعوت دی اور ساتھ ہی لکھا کہ اگر آپ اسلام قبول کریں گے تو آپ کی حکومت کو لمبی زندگی
حاصل ہوگی.حارث اس وقت قیصر کی فتح کے جشن کے لئے تیاری کر رہا تھا.حارث سے ملنے سے پہلے
شجاع بن وہب اس کے دربان یعنی مہتم ملاقات سے ملے.وہ ایک اچھا آدمی تھا اور اس نے شجاع کی
زبانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر فی الجملہ ان کی تصدیق کی مگر شجاع کو بتایا کہ اسے حارث
سے چنداں امید نہیں رکھنی چاہئے کیونکہ وہ قیصر سے ڈرتا ہے اور اس کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں کرے گا.چند دن کے انتظار کے بعد شجاع بن وہب کو رئیس غسان کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی اور انہوں نے
اس کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا.حارث نے خط پڑھ کر غصہ میں پھینک دیا اور کہنے
لگا.مجھ سے میرا ملک چھینٹے کی کون طاقت رکھتا ہے.بلکہ میں خود اس مدعی کے خلاف فوج کشی کروں گا
اور اگر مجھے یمن تک بھی جانا پڑے تو اسے پکڑ کر لاؤں گا اور اس نے اپنے سواروں کے دستے کو تیاری کا حکم
دے دیا.اور دوسری طرف قیصر کو خط لکھا کہ مجھے حجاز کے مدعی نے اس قسم کا خط لکھا ہے اور میں اس کے
خلاف فوج کشی کرنے لگا ہوں.اس خط کا جواب قیصر نے یہ دیا کہ فوج کشی نہ کرو اور مجھے آکر دربار کی
شرکت کے لئے ایلیا یعنی بیت المقدس میں ملو.اس کے بعد ایلیا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر
دحیہ کلبی کے ساتھ جو گزری اس کا ذکر قیصر والے خط کے بیان میں کیا جا چکا ہے اور رئیس غسان والا قصہ
یہیں ختم ہو گیا اور وہ مسلمان نہیں ہوا نے البتہ حدیث اور تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ مدینہ میں ایک عرصہ تک
اس بات کا خوف رہا کہ غسانی قبائل مسلمانوں کے خلاف کب حملہ کرتے ہیں.یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ عرصہ بعد حارث بن ابی شمر کا جانشین جبلہ بن ایہم جوریاست غسان
زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۵۷ و تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۴۳
: بخاری کتاب النکاح باب مَوْعِظَةُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا
زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۶۶
Page 944
۹۲۹
کا آخری فرمانروا تھا مسلمان ہو گیا اور حضرت عمر کے زمانہ میں مدینہ میں بھی آکر رہا.مگر جب اس نے
ایک غریب مسلمان
کو تھپڑ مار دیا اور اس پر حضرت عمر نے اسے ڈانٹا کہ حقوق کے معاملہ میں سب مسلمان
برابر ہیں تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا تو وہ زمانہ جاہلیت والے تکبر میں مبتلا ہوکر یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ کیا
میں اور ایک عام مسلمان برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اسی ارتداد کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے
رئیس یمامہ کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط چھا تبلیغی خط یمامہ کے رئیس ہورہ
بن علی کے نام بھجوایا گیا.اس خط کو
لے جانے والے سلیط بن عمر وقرشی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں ہوذہ کو اسلام کی دعوت
دی مگر ہوذہ ایک متکبر مزاج انسان اور دنیا کا بندہ تھا اس نے بظاہر سلیط بن عمرو کی بڑی آؤ بھگت کی مگر
جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ میرا عربوں میں بڑا مقام ہے ( غالباً مراد یہ تھی کہ
میرا وجود آپ کے سلسلہ کے لئے بہت مفید ہو سکتا ہے ) آپ اگر میرے لئے وصیت کر جائیں کہ کچھ
حکومت کا حصہ آپ کے بعد مجھے بھی مل جائے تو میں مسلمان ہو سکتا ہوں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کا خط پڑھ کر غصہ سے فرمایا کہ ” ( یہ تو خدا کی چیز ہے) اگر ہوذہ مجھ سے کھجور کا ایک کچا دا نہ بھی مانگے تو
میں اسے نہیں دوں گا.‘ اس کے بعد ہو زہ بن علی فتح مکہ کے بعد کفر کی حالت ہی میں مر گیا.اور جب آپ
کو ہوذہ کی موت کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یمامہ کے علاقہ میں عنقریب ایک جھوٹا نبی پیدا ہوگا
جو میری وفات کے بعد قتل کیا جائے گا.کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ا سے کون قتل کرے گا ؟ آپ نے
فرمایا.تم اور تمہارے ساتھی اور کون ؟ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی مسلیمہ کذاب کے
ظہور میں پوری ہوئی جو مسلمانوں کے خلاف بعض خونریز لڑائیاں لڑنے کے بعد حضرت ابوبکر کے
عہد خلافت میں ہلاک ہوا.بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کی طرف سلیط بن عمرو کوبھجواتے
ہوئے ان کے سپر د دو تبلیغی خط کئے تھے.ایک ہوذہ کے نام اور دوسرا ثمامہ بن اثال کے نام.مگر یہ درست
نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ اسی کتاب میں دوسری جگہ بیان کیا جا چکا ہے.ثمامہ اس سے پہلے ایک سریہ میں قید
ہو کر مدینہ میں مسلمان ہو چکے تھے.پس اگر اس موقع پر شمامہ کو کوئی خط لکھا گیا تو یقیناً وہ تبلیغ کا خط نہیں ہوگا
بلکہ اس تحریک کے لئے ہوگا کہ وہ آپ کے خط کو ہوزہ تک پہنچانے اور اسے تبلیغ کرنے میں سلیط بن عمرو کی
ل : تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۴۳، ۶۷
زرقانی جلد۳ و تاریخ خمیس جلد ۲
Page 945
۹۳۰
امداد کرے.یہی وہ تشریح ہے جو علامہ زرقانی نے اس اختلاف کی کی ہے.اوپر کے چھ تبلیغی خط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معابعد بعض روایتوں کے مطابق
ایک ہی دن میں اور دوسری روایتوں کے مطابق اوپر تلے لکھ کر بھجوائے تھے.ان کے بعد جو خط لکھے گئے
وہ کچھ وقفہ کے بعد لکھے گئے تھے اور ہم انہیں انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پر بیان کریں گے.اوپر کے چھ تبلیغی خطوط سے اس بات کے اندازہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے قریش کے ساتھ صلح ہوتے ہی اپنی پہلی فرصت میں کس درجہ مستعدی اور انہماک کے ساتھ تبلیغ کا فرض
ادا کیا.گویا آپ نے ایک آن واحد میں عرب کے چاروں اطراف میں اسلام کا بیج بکھیر دیا.آپ کے
اس فعل سے آپ کے اُس قول پر بھاری روشنی پڑتی ہے جو آپ نے ایک جنگی مہم سے واپسی پر فرمایا کہ:
رَجَعْنَا مِنَ الْجَهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجَهَادِ الْأَكْبَرِ
یعنی اب ہم تلوار کے چھوٹے جہاد سے تبلیغ و عبادت کے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں.“
حق یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خدمت دین اور خدمت خلق میں خرچ ہوتا تھا اور حالات کے
ماتحت جس جس قسم کے کام کی ضرورت پیش آتی تھی آپ کی روح اس کی طرف اس طرح لپکتی تھی جس
طرح ایک محبت کے جذبات سے بھری ہوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے دوبارہ پانے پر اس کی طرف
لپکتی ہے.دنیا آپ کے لئے ایک سفر کی منزل سے زیادہ نہیں تھی اور اپنے آسمانی آقا کی خدمت اور اس کی
عبادت اور اس میں ہو کر مخلوق کی محبت سب کچھ تھی.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَبَارِ وَسَلِّمُ.بعض متفرق واقعات جو تبلیغی خطوط آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف
بادشاہوں کے نام لکھے گئے ان کے لکھے جانے کی تاریخ کے
جوئے اور شطرنج کی ممانعت متعلق کسی قدر اختلاف ہے.یعنی بعض روایات میں ان کی تاریخ
ذوالحجہ ۶ ہجری بیان ہوئی ہے اور بعض میں محرم کے ہجری بیان ہوئی ہے مگر بہر حال اس بات میں کسی کو
اختلاف نہیں ہے کہ یہ چھ تبلیغی خط جو اوپر درج کئے گئے ہیں صلح حدیبیہ کے معابعد لکھے گئے اس لئے میں
نے انہیں ۶ ہجری کے واقعات میں درج کر دیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے دور دراز کے سفروں پر
ایلیچیوں کا جانا اور پھر جواب لے کر وہاں سے واپس آنا لازماً کافی وقت چاہتا تھا اس لئے خواہ یہ خطوط
لے دیکھو زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۶۶، ۳۶۷
بیہقی.نیز دیکھوسورۃ الفرقان آیت ۵۳
ملاحظہ ہوا بن سعد وطبری و زرقانی
Page 946
۹۳۱
۶ ہجری کے آخر میں لکھے گئے ہوں یا ۷ ہجری کے شروع میں بہر حال ان کے جوابات ۷ ہجری میں
موصول ہوئے لیکن سارے متعلقہ حالات کو ایک جگہ بیان کرنے کے خیال سے میں نے ان خطوط کو
ہجری کے واقعات میں درج کر دیا ہے.↓
اسی سال میں یعنی ۶ ہجری کے دوران میں حضرت عائشہ کی والدہ ام رومان کی وفات ہوئی.ام رومان جن کا نام زینب تھا.پہلے عبداللہ بن منجرہ کے نکاح میں تھیں اور عبداللہ کی وفات کے بعد
حضرت ابو بکر کے نکاح میں آئیں اور انہیں کے بطن سے عبدالرحمن بن ابو بکر اور حضرت عائشہ پیدا
ہوئے یا اُم رومان ایک بہت نیک مگر سادہ مزاج عورت تھیں لیکن حضرت ابوبکر خلیفہ اول کی بیوی اور
حضرت عائشہ کی ماں ہونے کی وجہ سے انہیں تاریخ اسلام میں جو امتیاز حاصل ہوا ہے وہ کسی بیان کا محتاج
نہیں.جب وہ قبر میں اتاری جارہی تھیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص نے جنت کی
کوئی حور دیکھنی ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے..یہ ایک بہت سادہ فقرہ ہے مگر اس سے پتہ لگتا ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جنت کی حوروں سے مراد ناز و ادا والی خوبصورت لڑکیاں نہیں تھیں
جو عالم آخرت میں پیدا کی جا کر مومنوں کے ساتھ جنت میں رکھی جائیں گی بلکہ اس سے مراد دنیا کی ان
پاک عورتوں کی روحیں ہیں جو جنت میں نیک لوگوں کی رفیق بنیں گی اور گو جنت میں ہر روح زندگی کے
کمال کی حالت میں جوان بنا کر داخل کی جائے گی ہے مگر بہر حال اس سے ظاہر ہے کہ جنت کی جنسی
رفاقت روحانی ہوگی نہ کہ جسمانی.شراب کی حرمت بھی بعض لوگوں کے نزدیک ۶ ہجری میں ہوئی لیکن جیسا کہ ہم اس کتاب کے حصہ دوم
میں بیان کر چکے ہیں ہمارے نزدیک اس کی حرمت میں غزوہ احد کے بعد ہجری کے آخر یا ۴ ہجری کے
شروع میں ہوئی تھی.اور یہی اکثر مسلمان محققین کا خیال ہے.عقلاً بھی میرے نز دیک شراب جیسی
گندی چیز جو کئی دوسری بدیوں کی ماں ہے اس کی حرمت میں ہجرت کے بعد زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی.شراب کی حرمت کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید فرماتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ
جس دسترخوان ( یا میز ) پر کوئی اور شخص شراب پی رہا ہو تمہیں اس دستر خوان پر بھی نہیں بیٹھنا چاہئے.3
زرقانی جلد ۳ حالات حضرت عائشہؓ ہے : تاریخ میں حالات ۶ ہجری سے : تاریخ کبیر مصنفہ امام بخاریؒ
بحوالہ زرقانی حالات حضرت عائشہ وابن سعد بحوالہ تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۳۹ ۴ : سورة الواقعه آیت ۲۳ ۲۴ و تر مندی
۵: ملاحظہ ہو کتاب طذ ا حصہ دوم صفحه ۳ ۵۷ تا صفحه ۵۷۵ ۱ : ابوداؤ د کتاب ۲۶ باب ۱۸ مسند احمد بن حنبل جلد اصفحه ۲۰
Page 947
۹۳۲
اسی سال بعض اقوال کے مطابق جوا بھی حرام کیا گیا.جوئے سے مراد ا تفاق کی کھیل ہے جس میں
آمدنی کی بنیا د محنت یا ہنر پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ محض اتفاقی حالات پر مبنی ہوتی ہے اور چونکہ ایسی آمد
میں وقت لگانا کیریکٹر کی تباہی کے علاوہ ملکی دولت کے توازن کو بھی بر باد کرنے کا موجب ہوتا ہے
اس لئے اسلامی شریعت نے کمال دانش مندی کے ساتھ جو ابھی حرام قرار دیا ہے.بیشک جلد باز انسان
آزادی کی رو میں بہہ کر ہر قسم کی پابندی سے گھبراتا ہے لیکن اس میں ذرہ بھر بھی شبہ نہیں کہ جو پابندیاں
اسلام نے مسلمانوں پر لگائی ہیں وہ سراسر ان کے فائدہ کے لئے ہیں اور جوئے کی حرمت بھی اسی اصول
کے ماتحت آتی ہے..اسی سال شطرنج کی کھیل بھی ممنوع قرار دی گئی ہے کیونکہ ایک تو وہ بالعموم جوئے کا بہانہ بن جاتی ہے
اور دوسرے اس میں اتنا انہماک پیدا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے مفید شعبوں کی طرف سے غافل ہو جاتا
ہے.اسلام یقیناً انسان کو جائز تفریحوں سے نہیں روکتا لیکن وہ اس بات سے ضرور روکتا ہے کہ انسان
بالکل ہی شتر بے مہار بن کر جو چاہے کرتا پھرے اور اپنی زندگی کے مفید پہلوؤں کو تباہ کر لے اور چونکہ
شطرنج کی کھیل اپنے اندر یہ دو بھاری نقصان کے پہلو رکھتی ہے یعنی ایک تو حد سے زیادہ انہماک جو شطرنج
کے کھلاڑی کو گو یا دنیا و مافیہا سے غافل کر دیتا ہے اور دوسرے جوئے کی طرف میلان کیونکہ شطرنج بھی اکثر
جوالگا کر کھیلا جاتا ہے اس لئے کمال حکمت سے اسلام نے اس کھیل سے روک دیا ہے.دراصل اسلام کے
فلسفہ شریعت میں صرف یہی بات داخل نہیں کہ جو چیز اپنی موجودہ صورت میں بُری ہے صرف اسی کو روکا
جائے بلکہ یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز خواہ وہ اپنی موجودہ صورت میں بُری نہ ہولیکن اگر وہ عام حالات
میں انسان کو برائی کی طرف کھینچتی ہے اور اس کی یہ کشش غیر معمولی غلبہ رکھتی ہے تو اسے بھی روک دیا جاتا ہے.یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شراب وغیرہ کے متعلق اصولی طور پر فرماتے ہیں کہ:
مَا اَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
یعنی ” جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی جائز نہیں.“
سورة المائدة آیت ۹۱ نیز تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۳۰
: دیکھو کتاب لهذا حصہ سوم صفحه۷۹۰
مسلم کتاب ۴۱ حدیث ۰ او مسند احمد جلد ۲ صفحه ۶۵ او تاریخ خمیس حالات ۶ ہجری
: مسند احمد بن حنبل
Page 948
۹۳۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ایک نہایت گہرے اور لطیف نفسیاتی فلسفہ پر مبنی ہے کہ
دنیا میں بعض بدیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اکثر انسان ان میں ایک دفعہ قدم رکھ کر پھر آگے بڑھنے سے رک
نہیں سکتے.اور ہر پہلا قدم دوسرے قدم کی طرف دھکیلتا ہے مگر افسوس ہے کہ بہت کم لوگ اس فلسفہ کو سمجھتے
یا اس کی قدر کرتے ہیں.( اس جگہ حصہ سوم کی جز واؤل ختم ہوئی )
Page 950
۹۳۵
بسم الله الرحمن الرحيم
میری تصفیف کی اس وقت تک خدا تعالی کے فضل سے
دو جلدیں مکمل اور تیسری جلد جز و أ شائع ہو چکی ہیں.یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل واحسان ہے کہ
اس نے مجھے اس کتاب کی تصنیف کی توفیق عطا فرمائی اور میری اس کوشش کو قبولیت سے
نوازا.فالحمد اللہ علی ذالک.میں نے کچھ عرصہ سے سیرۃ خاتم النبیین کی تیسری جلد کے بقیہ حصہ کے مضامین کی فہرست
تیار کر کے مرتب کر رکھی تھی جواب الفضل میں شائع کرنے کی غرض سے بھجوا رہا ہوں.اس
اشاعت کی سہ گو نہ غرض ہے.اول یہ کہ تا مجھے اس کتاب کی تکمیل کی یاد دہانی ہوتی رہے.دوسرے یہ کہ اگر خدانخواستہ میں اسے اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکوں تو خدا کا کوئی اور
بندہ اسے انہی لائنوں پر مکمل کر دے اور میں بھی اس کے ثواب میں حصہ دار بن جاؤں.اور تیسرے یہ کہ اگر کسی دوست کے خیال میں اس فہرست کی تکمیل کے متعلق کوئی مفید
تجویز آئے یعنی ان کی رائے میں اس فہرست میں کوئی عنوان زیادہ ہونے والا ہو یا ترتیب
بدلنے والی ہو یا کوئی اور تبدیلی ضروری ہو تو وہ مجھے مطلع فرما کر اس تصنیف کے ثواب میں
شریک ہو جائیں.بالاخر دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اس ضروری تصنیف کی تکمیل کے لئے دعا بھی
فرما ئیں کیونکہ ہر امر حقیقتا خدا تعالیٰ ہی کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ معلق ہوتا ہے.خاکسار را قم آغم
مرزا بشیر احمد عفی عنہ
ربوه ۳۱ /جنوری ۱۹۵۵ء
( منقول از روزنامه الفضل ربوه - شماره ۲۰ فروری ۱۹۵۵ء)
Page 952
۹۳۷
سيرة خاتم النبیین کے بقیہ حصہ کے مجوزہ عناوین
ماه
از اوائل سن سے ہجری تا وفات
واقعات سن ۷ ہجری
واقعہ
ماہ محرم ۷ ہجری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا مزعومہ واقعہ اور اس کی حقیقت
سریه ابان بن سعید بطرف نجد
ابو ہریرہ کا اسلام لانا ( جو روایتوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کے
سب سے بڑے راوی ہیں.)
کیفیت
غزوہ ذی قرد یعنی غائبہ ( سلمہ بن اکوع کو رسول پاک کا لطیف ارشاد ( عام مؤرخین اسے ۴ ہجری میں
بیان کرتے ہیں مگر حدیث سے
ے ہجری ثابت ہوتا ہے.)
ماہ محرم وصفر ( یعنی غزوہ خیبر جو عرب کے یہودیوں کا سب سے بڑا گڑ ھ تھا.امام مالک کے نزدیک یہ غزوہ
اگست ۶۲۸)
//
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوز ہر دے
کر قتل کرنے کی ناکام کوشش
کنانہ بن ابی الحقیق کے قتل کا واقعہ اور غیر مسلم مؤرخوں کے
اعتراضات کارد
حضرت صفیہ کی شادی جو اسرائیلی قوم سے تھیں ( حضرت صفیہ کی
خواب اور اس کی تعبیر.اس خواب
کا معجزہ شق القمر سے تعلق )
بعض فقہی مسائل کی تشریح یعنی پالتو گدھے کا گوشت.درندوں کا
گوشت.متعہ - استبراء - بیچ.مال غنیمت وغیرہ
سنہ ۶ ہجری میں ہوا تھا)
Page 953
۹۳۸
ماه
واقعہ
ماہ محرم و صفر ( یعنی اہل فدک کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت
اگست ۶۲۸ ) (فدک کے متنازعہ مسئلہ کی تشریح)
غیر مسلموں کے ارض حجاز میں رہنے کے بارہ میں اسلامی حکم
(اور ضمناً ارض حرم کے متعلق احکام)
جمادى الآخرة غزوہ وادی القریٰ
نماز فجر کا بے وقت ادا ہونا
بعض کے نزدیک یہ فتح مکہ
کے بعد کا واقعہ ہے)
اس معاملہ میں اختلاف ہے،
یہ واقعہ غزوہ تبوک میں ہوایا کہ
شعبان
مہاجرین حبشہ کی واپسی (حضرت جعفر بن ابی طالب کی واپسی پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی خوشی )
حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان کا رخصتانه
خسرو پرویز کسری شاہ ایران کا مارا جانا
غزوہ ذات الرقاع
صلوۃ خوف اور مختلف حالات میں اس کے مختلف طریق
اسلام میں سیرت کے پہلو پر زور اور حالات کی رعایت ملحوظ رکھنے
کے متعلق اصولی نوٹ.اسلامی شریعت کے ٹھوس اور لچکدار حصے
حضرت ماریہ قبطیہ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنا
لونڈیوں کے مسئلہ پر ایک اصولی نوٹ
سریہ حضرت عمر بطرف تربته
سریہ بشر بن ساعد بطرف بني مرة
حدیبیہ سے واپسی پر )
( مؤرخین میں اس کی تاریخ
کے متعلق اختلاف ہے)
Page 954
۹۳۹
ماه
رمضان
شوال
واقعہ
سریہ غالب بن عبد اللہ لیشی بطرف میفعہ اور حضرت اسامہ کا واقعہ.در باره قتل جہری مسلمان
سریه بشر بن ساعد بطرف یمن و جبار
سریہ ابن عمر بطرف نجد
ذو قعدہ فروری ۶۲۹ء عمرة القضاء جو صلح حدیبیہ کے نتیجہ میں ادا کیا گیا.حضرت میمونہ کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی
"/
یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شادی تھی)
بعض کے نزدیک سریہ ابان
بن سعید اور یہ ایک ہی ہیں)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں اور ازواج مطہرات کے مزید شادیوں پر پابندی
متعلق ایک مجموعی نوٹ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعد آ پکی ازواج کے متعلق یہ
پابندی کہ آپ کے بعد اور کسی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلی زندگی پر نوٹ ( معاشرہ
نان و نفقہ.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارہ کا ذریعہ وغیرہ)
سریہ ابن ابی العوجا بطرف بنی سلیم
بلا تعین ماہ جبلہ ابن الا یھم رئیس غسان کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
تبلیغی خط اور اس کا مسلمان ہونا ( مگر حضرت عمرؓ کے زمانہ میں یہ شخص
پھر مرتد ہو گیا )
واقعات سن ۸ ہجری
ماه صفر ۸ هجری خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کا اسلام لانا ( خالد اور عمرو بن عاص
کی تاریخ اسلام میں نمایاں حیثیت )
سے شادی نہ کریں)
//
سریہ غالب بن عبداللہ بطرف بنی ملوح
Page 955
۹۴۰
ماه
واقعہ
ماه صفر ۸ ہجری سریہ غالب بن عبداللہ بطرف فدک
مسجد نبوی میں منبر بنانے کی تجویز اور حنین الجذع کا واقعہ
فلسفی منکر حنانه است از حواس انبیاء بیگانه است)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کو ایک شخص کے قتل کرنے کے
جرم میں قتل کی سزادینا ( یہ اسلام میں قتل کی پہلی سزا تھی )
اسلامی شریعت میں قانون قصاص پر اصولی نوٹ
ربیع الاول سر یہ شجاع بن وہب بطرف بنی عامر
//
سریہ کعب بن عمر بطرف ذات الملاح
جمادی الاول عرب کی شمالی سرحد میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور بیرونی
ستمبر ۶۲۹ء ممالک کے خطرات کا آغاز
غزوہ موتہ.( زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن
رواحہ کی شہادت )
جمادى الآخرة سریہ عمرو بن عاص بطرف ذات سلاسل اور سریہ ابو عبیدۃ کمک کی
صورت میں
سریہ ابو عبيدة بطرف السيف البحر (اس سریہ میں راشن بندی کی
رجب
(نومبر ۶۲۹) ضرورت پیش آئی اور خوراک کے متفرق ذخائر کو ایک جگہ جمع کر
دیا گیا)
شعبان
سريه ابوقتادة بطرف خضرة
رمضان
سریہ ابوقتادہ بطرف بطن اصنم
سریہ عبداللہ بن ابی حدر د بطرف غابه
غزوہ فتح مکه
جنوری ۶۳۰ ء حرم کی حدود میں اسلام کا پُر امن اور شاندار دا خلہ.عام معافی.بعض
خاص مجرمین ( جن پرقتل وغارت کا الزام تھا) کے قتل کا حکم.بیت اللہ
بعض مورخین کے نزدیک یہ
دونوں ایک ہی ہیں.
Page 956
۹۴۱
ماه
واقعہ
کے بتوں کا تو ڑا جانا.حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ، ابوسفیان ،
حکیم بن حزام صفوان بن امیہ ، عکرمہ بن ابو جہل ویرہ کا مسلمان ہونا.جنوری ۶۳۰ ء اس بات پر نوٹ کہ فتح مکہ کے بعد بھی مکہ کے کئی لوگ کفر پر قائم
شوال
"/
"/
رہے.مکہ سے بعث خالد بطرف عزا.عمرو بن عاص بطرف سواع.سعد بن زید بطرف مناۃ.سریہ خالد بطرف جذیمہ
اسلام کا ایک روحانی مذہب ہونا اور روحانیت پر ایک اصولی نوٹ
غزوہ حنین (حنین کے واقعہ میں مسلمانوں کے لئے ایک بڑا سبق تھا)
سریہ ابوعامر اشعری بطرف اوطاس
سری طفیل بن عامر بطرف ذوالکفین
فروری ۶۳۰ء غزوہ طائف
جعرانہ کے مقام میں غنائم کی تقسیم.بعض انصار کی طرف سے
اعتراض اور اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب.ایک لطیف
روحانی منظر.اپنے رضاعی عزیزوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا انتہائی مربیانہ سلوک وغیرہ
رئیس بحرین کی طرف تبلیغی خط اور اس کا جواب
اسلام میں بریکار لوگوں کے گزارہ کا استثنائی انتظام
جزیہ پر ایک اصولی نوٹ
ذوالحجہ ابراہیم ابن رسول اللہ کی ولادت
(اپریل ۶۳۰ ء) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرب کے مختلف
اطراف سے وفود کی ابتدا
بلاتین ماہ حضرت زینب بنت رسول اللہ کی وفات
زکوۃ کا فرض ہونا
Page 957
۹۴۲
ماه
واقعہ
بلا تعین ماه نظام زکوۃ کی حقیقت اور اس کی غرض وغایت
واقعات سن ۹ ہجری
محرم
قصہ عام الوفود یعنی سال بھر وفدوں کا مدینہ میں آتے رہنا اور اسلام
کی اشاعت میں غیر معمولی توسیع
بعث عینیہ بن حصن بطرف بنی تمیم
محرم یا صفر بعث ولید بن عقبہ بن ابی معیط بطرف بنی مصطلق
"
سریہ ابن عویجه بطرف بنی عمرو
بعث قطبہ بن عامر بطرف خشم
ربیع الاول بعث ضحاک بطرف بنی کلاب
بعث علقمہ بن محزر بطرف حبشہ
ربیع الآخر بعث حضرت علی بطرف فلس
بعث عکاشہ بن محصن بطرف الحباب
کعب بن زہیر شاعر کا مسلمان ہونا
مشہور قصیدہ بردہ
(حاکم کے نزدیک یہ ماہ صفر
میں ہوا )
ماہ ربیع الثانی اور بعض کے
نزدیک سن ۸ هجری)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے ایک ماہ ہجر کرنا (ابن حبان کے نزدیک یہ واقعہ
رجب
غزوہ تبوک جسے غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں.ستمبر ۶۳۰ ء (غزوہ موتہ کے بعد روم اور ایران کے ساتھ جنگ کا یہ پہلا قدم تھا)
//
سریہ خالد بطرف اکیدراز مقام تبوک
وفات عبداللہ ذی البجا دین تبوک میں
سن ۸ ہجری میں ہوا اور ابن حجر
نے بھی یہی کہا ہے )
Page 958
۹۴۳
ماه
ستمبر ۶۳۰ ء ہرقل کے نام خط از تبوک
واقعہ
رمضان منافقین کا فتنہ اور مسجد ضرار کا گرایا جانا اور منافقین کی پردہ دری
//
قصه سزا و معافی کعب بن مالک وغیرہ
قصہ لعان اور واقعہ عویمر (مسئلہ لعان کے متعلق اسلامی حکم )
قبیلہ بنو ثقیف کا مسلمان ہونا
کیفیت
( یہ قیصر کے نام دوسرا خط تھا)
//
بلا تعین ماہ ملوک حمیر کے نام حط
لات کے بت کا منہدم کیا جانا
اس واقعہ کی تاریخ قابل تحقیق
ہے)
غامد یہ عورت کا رجم
رجم کی سزا پر ایک اصولی نوٹ.( کیا رجم کی سزا حقیقتاً اسلامی |
سزا ہے)
نجاشی بادشاہ حبشہ کی وفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نجاشی
کا غائبانہ جنازہ پڑھنا
اس بات پر نوٹ کہ یہ کون سانجاشی تھا
مسئلہ جنازہ کے متعلق اصولی نوٹ
وفات أم كلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
زکوۃ کی وصولی کے لئے عمال کا تقرر
ذ وقعده عبد اللہ بن ابی رئیس المنافقین کی موت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا جنازہ پڑھنا اور حضرت عمرؓ کا اعتراض
حج کا فرض ہونا
علامہ ابن قیم کے نزدیک ان
کی وفات شعبان میں ہوئی تھی)
(زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۴۳ و
زادالمعاد جلد اصفحه ۱۸۰)
Page 959
۹۴۴
ماه
ز وقعده حج پر اصولی نوٹ
واقعہ
ذ وقعدہ و مارچ حضرت ابوبکر کی اقتدا میں مسلمانوں کا پہلا حج
۶۱ء
بلا تعین ماہ اسلام میں قمری اور منشی نظام ( یعنی سہولت عامہ کے لحاظ سے کسی امر
میں قمری نظام اور کسی میں تشسی )
اہل فارس کا کسری شہر یار کو قتل کر کے اس کی لڑکی بوران کو تخت پر
بٹھانا
(علامہ زرقانی نے سفر کی ابتدا
بھی ذوالحجہ میں لکھی ہے )
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر نوٹ کہ عورت
کو بادشاہ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
بنانے والی قوم کامیاب نہیں ہوگی.واقعات سن ۱۰ ہجری
محرم
عدی بن حاتم طائی کا مسلمان ہونا
ربیع الاول بعث ابو موسی اشعری بطرف یمن
بعث معاذ بن جبل بطرف یمن
بعث خالد بن ولید.بطرف نجران
یہ ارشاد انفرادی حکومت کے
زمانہ کا ہے اس لئے یہ خیال نہ
کیا جائے کہ یورپ کے بعض
ممالک نے عورت کے حاکموں
کے زمانہ میں خاص ترقی کی ہے
کیونکہ یورپ میں اصل حکومت
قوم کی ہوتی ہے اور ملکہ برائے
نام ہوا کرتی ہے.گو پھر بھی
بعض نقائص پیدا ہو جاتے ہیں)
(یا شعبان سن ۹ ہجری)
( يا ربيع الآخر )
Page 960
۹۴۵
ماه
واقعہ
ربیع الاول وفات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسوف شمس
( جون ۶۳۱ء) (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کایہ فرمانا کہ اگر میرا بچہ زندہ رہتا تو نبی بنتا)
بلا تعین ماہ بعث جریر بن عبد الله بطرف ذوالکلاع
رمضان
بعث ابوعبیده بطرف نجران
قصه بدیل و تمیم الداری وابن صیاد
دجال کے متعلق اُصولی نوٹ
جبرائیل کا تمثیلی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
حاضر ہو کر مسائل دریافت کرنا
بعث حضرت علی بطرف یمن
بلا تعین ماہ سود کی ممانعت
//
اشتراکیت یعنی کمیونزم پر ایک اُصولی نوٹ
ابو عامر راہب کی موت
وفات باذان والی یمن
//
نزول احکام بابت استیذان
ذوالقعدہ وذوالحجہ (حجۃ الوداع جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات
( مارچ ۶۳۲ ء) کے قریب کے خیال سے مسلمانوں کو الوداع کہا.//
آیت الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
کانزول
اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ( سابقہ مذاہب کے متعلق اسلام کا مسلک.پنج ارکان اسلام.مسئلہ ختم نبوت.اسلام کی عالمگیر شریعت - شریعت
کے ٹھوس اور لچکدار حصے وغیرہ.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقعہ پر
بلا تعین ماہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جَوَامِعُ الكَلِم عطا کئے گئے.
Page 961
۹۴۶
ماه
واقعہ
بلا تعین ماه آپ کے خاص خاص امتیازی کلمات
واقعات سن ۱۱ ہجری
محرم و فد نخع از میمن ( یہ آخری وفد تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
صفر
سامنے پیش ہوا )
مدفونین جنت البقیع کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا
( نیز اُحد میں جا کر شہداء اُحد کے لئے دعا )
سریہ اسامہ بن زید ( یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری
(مئی ۶۳۲ ء) سریہ ہے گو اس کی روانگی بھی آپ کی وفات کے بعد ہوئی.صفر یا ربیع الاول اسود عنسی کذاب کا ظہور
"
مسیلمہ کذاب کا ظہور (سجاح متنبیہ کا واقعہ )
طلیحہ بن خویلد کا ظہور
الہی سلسلوں میں ارتداد پر ایک اصولی نوٹ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کا آغاز (مرض کیا تھی.کتنے دن رہی.کیا علاج کیا گیا وغیرہ وغیرہ)
قرطاس کے واقعہ کی تشریح
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر کو اپنی جگہ امام الصلوۃ
مقرر کرنا.//
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے فرمانا کہ میں نے
ارادہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر کے متعلق خلافت کی وصیت لکھ دوں
مگر پھر اسے خدا اور مومنوں پر چھوڑ دیا.ربیع الاول افاقہ قبل وفات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں تشریف
//
لے جا کر صحابہ سے باتیں کرنا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام
Page 962
۹۴۷
ماه
ربیع الاول وصال اکبر
( جون ۶۶۳۲)
"/
"/
"
"/
واقعہ
مسجد نبوی میں صحابہ کا غم و اندوہ.حضرت عمر کا پیچ و تاب کھانا.حضرت ابوبکر کا خطبہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - يَزاَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا
قَدْ مَاتَ -
اسلام کا سب سے پہلا بلکہ واحد اجماع
سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ اور حضرت ابوبکر خلیفہ اول کی ابتدائی بیعت
مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر کی عام بیعت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل میکنین.جنازہ.قبر اور تد فین وغیرہ
کیا آنحضرت کا جنازہ اکٹھا با جماعت پڑھا گیا.اگر نہیں تو کیوں؟
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بحساب نظام قمری و شی.آنحضرت کا ورثہ ( تشریح حديث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ )
شمائل نبوی کی ایک اجمالی جھلک
محمد مفلح یعنی سب نبیوں میں سے زیادہ کامیاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کتاب کا خاتمہ
Page 964
۹۴۹
اللہ علیہ وسلم
سيرة خاتم النبین حصہ دوم کے متعلق بعض آراء
حضرت امیر المؤمنین خلیفہ اسی امام جماعت احمدیہ کی رائے اس سال ایک کتاب سلسلہ کی
طرف سے بیش قیمت شائع
ہوئی ہے جس کا نام سیرۃ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دوم ہے جو میاں بشیر احمد صاحب کی تصنیف ہے.میں نے اس کا بہت سا حصہ دیکھا ہے اور اس کے متعلق مشورے بھی دیئے ہیں.میں سمجھتا ہوں رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیر تیں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے یہ بہترین کتاب ہے.اس تصنیف میں اُن
علوم کا بھی پر تو ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ حاصل ہوئے.اس کے ذریعہ انشاء اللہ ا
سلام
کی تبلیغ میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی.سرسکندر حیات خان سابق ممبر مال گورنمنٹ پنجاب کی رائے ”سیرۃ خاتم النبین کی تکمیل
غیر مذاہب تک سرور کائنات
کے صحیح معاشرتی و انتظامی حالات واضح کرنے کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگی.انشاء اللہ.بالخصوص ان
بے بنیاد الزامات جن کے متعلق اکثر غیر مسلم بوجہ نا واقفیت یا تعصب بیجا نکتہ چینی کرنے کے عادی ہیں
اُن کے متعلق نہایت خوبی اور وضاحت سے تاریخی واقعات کا حوالہ دے کرمسکت جواب دیا گیا ہے.اگر اس کتاب
کا ترجمہ انگریزی اور یورپ کی دیگر زبانوں میں ہو جائے تو میرے خیال میں اسلام کی ایک
بڑی بھاری خدمت ہوگی.“
سیٹھ عبداللہ ہارون ایم.ایل.اے تاجر کراچی کی رائے ”میری رائے میں اس زمانہ میں
جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرۃ کی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اُن میں سے یہ ایک بہترین کتاب ہے.امید ہے کہ یہ کتاب
مسلمانان ہند کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگی.ڈاکٹر شیخ محمد اقبال بار ایٹ لاء لاہور کی رائے ”اس تصنیف میں بعض اہم مباحث پر عمدہ
بحث کی گئی ہے.جناب مولوی الف دین ایڈووکیٹ ضلع سیالکوٹ کی رائے ”عہد حاضر میں سیرۃ پر کئی کتا ہیں
لکھی گئی ہیں اور حق یہ ہے کہ
Page 965
ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، مگر اس کتاب کی نسبت جو نہایت محنت اور جانفشانی سے
لکھی گئی ہے
اگر یہ کہا جائے کہ ”گل سرسبد ہے تو مبالغہ نہ ہو گا.خدائے بلند و برتر نوجوان میرزا کی ہمت میں برکت
دے کہ انہوں نے اس مبارک تالیف سے اسلام اور اسلامیوں کی ایک اہم خدمت سر انجام دی ہے.نواب اکبر یار جنگ بہادر حج ہائیکورٹ حیدر آباد دکن کی رائے ”میری نظر میں سیرت کی اُردو
تالیف میں بے مثل کتاب ہے.جنگ، غلامی ، تعدد ازدواج پر اس قدر دل نشین اور سیر کن بحث کی گئی ہے کہ دل سے دعا نکلتی ہے.ایک زمانہ میں ان مضامین پر میں نے کافی غور کیا ہے اور جو کچھ اس کے متعلق مل سکتا تھا سب پڑھ ڈالا
ہے.میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ان مضامین کا حق ادا کر دیا ہے.مولانا سید سلیمان ندوی کی رائے سيرة خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد دوم موصول ہوئی.شکریہ.مباحث ضرور یہ پڑھے.اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی
اس خدمت کی جزائے خیر دے اور مزید سعادت عطا فرمائے.اختلاف واتفاق کی بحث الگ ہے مگر
اس میں شک نہیں کہ آپ نے اپنی اس تصنیف میں محنت اُٹھائی ہے“.ایڈیٹر رسالہ ”المعارف‘اعظم گڑھ (یو.پی ) کار یویو "سيرة خاتم النبین قادیان کی
جماعت احمدیہ کی جانب سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ میں شائع ہوئی ہے.اس کا حصہ دوم زیر نظر ہے جس میں آپ کی
مدنی زندگی سن ۵ ہجری تک پیش کی گئی ہے.کتاب کا نمایاں وصف مستشرقین اور غیر مسلم مؤرخین کے
اعتراضات کا رد ہے...اس میں شبہ نہیں کہ کتاب محنت اور کوشش سے لکھی گئی ہے.ایڈ میٹر اخبار ”سچ ،لکھنؤ کار یویو "سيرة خاتم النبيين حصہ دوم بہت مفصل و مشرح ہے اور اس
سیر نما
میں علاوہ واقعات تاریخی کے مسائل کا حصّہ بھی کثرت سے
آ گیا ہے.قانون ازدواج و طلاق ، غلامی، تعدد ازدواج ، جهاد وغیرہ کے مباحث خصوصاً مفصل ہیں اور
انگریزی خوان نو جوانوں کے حق میں مفید.معجزات پر بھی شافی بحث ہے...اور سب سے بڑی بات یہ
ہے کہ ان مسائل پر بحث کرتے وقت مصنف کا قلب تحقیقات فرنگ سے مرعوب و دہشت زدہ نہیں معلوم
ہوتا جیسا کہ اکثر متکلمین حال کا حال ہے...سرور کائنات کی ذات پر جمال تو وہ ہے جس نے خدا معلوم
کتنے بیگانوں تک کے دلوں کو موہ لیا ہے.اہل قادیان تو بہر حال کلمہ گو ہیں اُن کے کسی مصور کے قلم نے اگر
اس حسین و جمیل کی ایسی دلکش تصویر تیار کر دی ہے تو اس پر حیرت بے محل ہے.
Page 967
اسماء
مقامات
غزوات
کتابیات
اشاریہ
سیرت خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم
۲۴
۳۲
Page 968
۴۵
۴۵ ،۴۲،۲۴۹
۱۸۴
ام
اسماء
ابن الجوزی
ابن خلکان
ابن حجر عسقلانی
ابن حضرمی رئیس مکه
ابن حجر حافظ
ابن درید
ابن راہو یہ اسحاق بن ابراہیم
ابن سعد محمد
،۲۳۲،۲۱۴،۴۳،۳۹،۳۷
،۵۰۹،۵۰۷،۵۰۶،۴۸۳،۴۸۲۴۸۰،۳۷۲
،۶۸۳۶۲۱،۶۲۰ ، ۶۱۹ ،۵۸۷ ، ۵۸۳،۵۳۸،۵۲۱
،۸۱۰،۸۰۹،۸۰۸،۷۷۱ ،۷۷۰ ، ۷۶۴،۷۴۵
۸۳۵،۸۱۷،۸۱۲،۸۱۱
۲۸
،۱۳۵،۷۵،۱۹،۱۷ ،۱۶ ،
۴۷۱،۴۶۲،۴۴۸ ، ۴۴۴ ۴۳۸
۴۵
۲۰۴
12182.۶۶۳
۴۰،۲۹
۳۳
ابن صلاح صاحب المقدمه
ابن عباس
ابن عبدالبر
ابن عبدیالیل
ابن عربی محی الدین
ابن العرقه
ابن عدی ابواحمد عبد اللہ بن محمد
ابن عساکر
۲۲۸،۲۲۷ ۲۲۵ ،۲۲۴ ۲۲۰
۶۹۱
۸۰۰۷۹۹ ،۴۶۴
۴۸۸
۱۱۰ ۱۰۹ ۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰۳
۴۵۸،۴۵۴
آدم علیہ السلام
آدمی
آریہ آریہ ورت
آسیہ اہلیہ فرعون
آمنہ بنت وهب
ابراہام لنکن
ابراہیم علیہ السلام ۷۷،۷۶،۷۵،۷۴،۷۳،۶۹،۵۵،
۸۰ تا ۲۲۳،۲۲۱،۱۵۰،۱۲۳۰۸۹۰۸۷ ۲۲۵ تا ۲۷۹،۲۲۸
ابرا ہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۹۱۹،۱۲۱
۱۰۱تا ۱۰۳
۲۳۰،۲۰۷
۳۳
٣٣
۴۵
۴۴۳۰
،۳۰۰،۲۳۲،۲۱۵،۳۷ ،۳۶،۲۷
،۸۰۴،۵۸۷،۵۳۷،۵۰۷،۳۷۲
۹۰۶،۸۱۷،۸۱۱،۸۱۰،۸۰۸
۱۷۱،۳۷،۳۴
ابر ہستہ الاشرم
ابلیس
ابن ابی حاتم
ابن ابی شیبه
ابن ابی طی
ابن اثیر الجزری
ابن اسحاق.محمد
ابن جریر طبری
Page 969
۲۵۶،۲۵۵،۲۵۲ ۲۴۲ ، ۲۴۱ ، ۱۹۷ ، ۱۹۱ ،۱۷۵
،۴۷۹،۲۶۹،۲۶۷ ۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۲،۲۶۱
۸۰۸ ،۷۱۷ ،۱۶،۵۰۴،۴۸۷
۴۰۶
۲۴
ابوجبل رضی اللہ عنہ
ابو جیفہ رضی اللہ عنہ
۵۰۷
ابن عقبہ
ابن عمر رضی اللہ عنہ ۴۴۳،۳۳۰، ۸۰۴،۴۷۱،۴۶۲،۴۴۸
۵
22.۳۴
۳۱ ابو جعفر محمد بن جریر طبری
ابن قتیبه
ابن قیم
ابن کثیر اسماعیل بن عمادالدین
ابن ماجه محمد بن یزید
ابن المدینی علی بن عبد اللہ بن جعفر
ابن مردویه
۴۱ ابو جندل رضی اللہ عنہ
۳۳ ابو جہل عمر و بن ہشام
ابن مسعود
۵۰۲
ابن ندیم
ابن ہشام
۴۵
،۵۲۱،۵۰۵،۴۸۴ ،۴۸۳،۲۱۴،۳۹
۸۷۳٬۸۷۲،۸۶۲۸۶۱،۸۵۹
،۱۵۹،۱۵۵،۱۵۳،۱۳۱،۱۳۰
،۲۰۶،۱۹۳،۱۸۹،۱۸۸،۱۸۳،۱۸۲۱۷۶
۴۲۱،۴۱۰،۴۰۳،۲۴۳۲۴۲
۸۳۵،۸۱۷،۸۱۲،۸۱۱ ، ۶۱۵ ، ۶۱۴،۵۳۸،۵۳۷
ابی بن خلف
۵۶۰،۱۵۳
ابی بن کعب
،۵۲۵،۳۳۹،۳۱۰۷
۵۹۸،۵۶۴،۵۴۴
ابو حاتم محمد بن ادریس
ابن حبان
ابن حجر
ابو حذیفہ بن عتبہ
،۱۹۳،۱۸۹،۱۸۸،۱۸۳،۱۸۲
۴۱۲۰۴۱۰،۴۰۳ ،۲۴۳،۲۴۲،۲۰۶
۳۳
۶۸۳،۶۳۰،۶۲۱ ،۱۷۱
۴۵۷ ،۱۶۵،۱۴۱
ابواحمد بن حجش
ابو اسحاق
ابوامامہ اسعد بن زراره
۲۴۹،۲۴۷
ابوداؤد
ابوامیہ بن مغیرہ
ابوایوب انصاری
۵۶۴ ابوالحکم ( ابو جہل ) سید الوادی دیکھئے ابو جہل
سٹیڈالوادی
۱۷ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت
۱۲۳ ابوداؤد سجستانی
۳۲
۸۱۱،۵۳۷، ۴۴۶
۴۱ ،۲۴
ابوالبختری
ابو براء عامری
ابو برده
ابوبصیر دیکھئے عقبہ بن اسید ثقفی
ابوبکر صدیق عبداللہ بن ابی قحافہ
۳۱۰،۲۹۹،۱۸
۴۰۳،۱۸۸،۱۸۰،۱۵۲
۵۸۶،۵۸۴،۵۸۳،۵۸۲
۴۴۰،۴۳۵ ، ۴۳۴
ابو دا و دسلیمان بن اشعث
ابودجانہ
ابوالدرداء
ابن الدغنہ
۳۱
5
۵۵۲،۵۵۱
۳۱۰
۸۷۰
،۱۲۹ ،۹۶،۷
ابوذرغفاری
ابو رافع سلام بن ابی الحقیق
۱۷۵،۱۷۴
۶۲۸،۲۷۹،۲۱۰،۱۵۸
،۶۴۶،۵۹۳،۵۲۷
۸۳۰،۸۱۲
،۱۷۴،۱۶۳۱۵۹، ۱۵۸ ،۱۴۲،۱۴۱ ،۱۴۰،۱۳۸
Page 970
ابو رافع دیکھئے سلام بن ابی الحقیق
ابوالربیع
ابوز بید
ابوزید
ابوسعید خدری
ابوسفیان بن حرب
ابوعبد الرحمن یزید بن ثعلبہ
۵۰۷ ابو عبیدہ بن الجراح
۷۳۹
22.ابوعزه
ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم
۵۴۸ | ابو عفک
۲۴۹
۷۵۶،۷۵۵،۵۶۰،۳۱۰،۱۴۰
۵۶۹
۴۱۴
۵۰۴ تا ۵۱۰،۵۰۹،۵۰۷
۱۳۰،۱۱۸،۱۰۰، ۱۴۲،۱۴۱، ابو عمر و عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن اصلاح
۲۸
۴۵
۱۵۸
۱۵۴
۶۷۸،۶۷۶،۴۰۱
،۱۴۵ ،۱۲۲،۱۱۲،۱۰۶
۱۸۷ ،۱۶۰،۱۵۷ ،۱۵۳،۱۴۶
۴۳۷
۲۷۹،۲۱۰،۱۴۹
۵۳۰
۴۳۶
ابوالفداء
،۳۹۶،۳۹۵،۳۹۱،۳۸۴،۳۵۴ ،۳۱۶،۱۸۰،۱۵۵
،۴۴۹،۴۲۲،۴۲۱ ،۴۲۰،۴۱۹ ،۴۰۳،۳۹۸،۳۹۷
۵۶۱،۵۵۱،۵۴۵،۵۴۳،۵۲۶،۵۱۳،۵۱۲،۵۱۱، ابوفکیہ رضی اللہ عنہ
۶۱۰،۵۹۵،۵۹۴،۵۸۱،۵۶۸،۵۶۳،۵۶۲، ۶۴۷ ، ابو قیس بن فاکہہ
۶۶۹،۶۵۹،۶۵۸، ۸۳۴،۸۳۳،۷۵۲،۶۷۱،۶۷۰، ابولبا به بن منذر انصاری
۹۰۴٬۹۰۳٬۹۰۲،۸۷۵،۸۷۴،۸۴۳٬۸۳۵، ابولہب بن عبدالمطلب
ابو سلمہ بن عبد الاسد
۹۲۷ ،۹۲۶،۹۱۰،۹۰۶۹۰۵
۱۴۰، ۱۶۵ | ابو مسعود بدری
ابوسلمہ زہری ابن عبدالرحمن بن عوف ۱۶۴،۱۳۹، ابوموسی اشعری
۲۱۸،۱۶۵، ۳۱۰ ، ۳۳۵ ، ۴۵۰،۴۱۳،۴۱۲،۴۱۰، ابونائلہ
۸۰۴۷۱۸،۵۵۶۰۵۶۵ تا ۸۶۴۸۰۶ | ابونوار
ابو صفوان امیہ بن خلف
ابوصیفی بن ہاشم
۳۱۶،۳۱۵ ، ۴۲۵ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۹۸ ابوالبیشم مالک بن تیبان
ابو طالب بن عبدالمطلب ۱۱۲ ۱۱۹،۱۱۶،۱۱۳ ۱۲۰ ۱۲۱، ابوالیسر رضی اللہ عنہ
ابوطلحہ انصاری
ابو العاص بن ربیع
ابو عامر
۱۴۴،۱۲۶،۱۲۵، ۱۴۶ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶، ابویوسف یعقوب بن ابراہیم
۱۹۲،۱۸۸،۱۵۷ ۱۹۳ ۱۹۴ | ابویعلی
۵۷۴،۵۵۸ | احمد بن حجر عسقلانی ابوالفضل
۴۱۵،۱۹۵،۱۲۲، ۴۱۸، احمد بن حسین بیہقی
۷۵۷، ۷۵۸، ۷۶۰، ۷۶۲۷۶۱ احمد بن حنبل
۳۰۸ ،۵۵۰ احمد بن شعیب النسائی
۱، ۲۲،۱۷ تا ۲۴ ،۴۴۳
۲۵۵،۲۵۴،۲۴۹
۴۳۵
۳۸
۳۳
۲۹
۳۳
۴۰،۲۷ ،۲۶
۳۱
Page 971
۲۹ اسید بن حضیر رئیس اوس ۴۰۰ ، ۶۳۲،۶۳۱،۵۴۷، ۶۳۷
۸۳۲،۸۳۱،۸۳۰
۶۶۷ ،۶۴۷
۵۲۷
۷۹۸،۲۱۰
۸۰۶
۱۰۵،۱۰۳،۱۰۱
۱۶۵
۹۲۶۹۲۵،۹۲۳۱۶۵
۱۲۵،۱۱۲ ۱۱۱ ۱۱۰ ۱۰۴
۹۲۷ ،۹۲۶
۹۳۱،۱۹۷
۵۰۱،۱۵۲،۱۴۰
احمد بن عبداللہ الحلبی
احمد بن علی بن محمد بن علی بن حجر العسقلانی
۳۰ اسیر بن رزام
احمد بن محمد بن ابراہیم قاضی المعروف بابن خلکان ۴۲، ۴۵ اشجع
احمد بن یحی بن جابر ابوجعفر
اور لین
۳۸ اشرف
۲۲۸،۲۲۷،۲۲۱ | اشعر
الذہبی علامہ
اراشه
۴۲ اصبغ بن عمر کلبی
۱۸۳۱۸۲ | اصحاب الفیل
ارقم بن ابی ارقم
۱۴۶،۱۴۱ اصحمہ
ازد
اصحمہ نجاشی
الزرقانی محمد بن عبد الباقی بن یوسف
۴۴ ام ایمن
اساف
۶۸ ام حبیبه ام المؤمنین (رمله)
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ
۳۲۷، ۳۶۱، ۴۵۱ ام رومان ( زینب ) زوجہ حضرت ابو بکر
۸۶۵،۸۴۳،۵۹۷،۵۹۶
۵۵۵
۳۰۰
۵۵۹
۸۱۱،۸۱۰،۸۰۸
۱۲۲،۱۲۱
۵۳۹،۵۳۸،۵۲۴
۸۶۸،۵۳۷
۶۳۵
۶۰۷
۸۱۱،۲۴
اسحاق بن ابراہیم المعروف بابن راہویہ
۷۷۹،۵۴۸،۴۵۲ ام سلمه ام المؤمنین
۹۸ ام سلیط
ام سلیم والدہ انس بن مالک
۴۲۴ ،۲۴۸
اسد بن ہاشم
اسرائیل
اسعد بن زرارہ ابوامامه
۲۵۰،۲۴۹،۲۴۷ ، ام عبداللہ دیکھئے عائشہ ام المؤمنین ام
۳۰۱،۲۵۵،۲۵۱ | ام عماره
اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ۷۳،۵۵ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ام فضل زوجه عباس بن عبدالمطلب
۸۶،۸۵،۸۳٬۸۲،۸۱،۸۰۷۹،۷۸،۷۷، | ام قرفه
۸۷، ۹۲،۸۹٬۸۸، ۹۱۹،۵۱۴،۳۷۸ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۳۴
اسماعیل بن عمر ابن کثیر عمادالدین
اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ
اسود بن مطلب
اسود بن عبد يغوث
اسود بن یزید
۴۴۲،۱۴۲ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط
۱۸۰،۱۵۴ | ام سح
۴۲۰
ام ہانی رضی اللہ عنہا
۱۷ امام
Page 972
۸۱۳،۴۳۹،۲۹۵
۲۵۹
۵۱
۶۲۸
۶۲۸
۶۳۶
۳۳
۴۸۳
۶۲۶۱
۴۰۱
عرض حال
،۱۵۸،۱۴۲،۱۴۱
امامہ بنت زینب وابی العاص
امرء القیس
امیمہ بنت عبدالمطلب
امیہ بن ابی الصلت
امیہ بن خلف
امیہ بن عبد شمس
النسائی احمد بن شعیب
انس بن مالک رضی اللہ عنہ
۶۴۴
۷۶۲ براء بن عازب رضی اللہ عنہ
البراء بن معرور
۶۱۱
،۳۹۶،۳۳۴،۳۱۶،۳۱۵
۴۲۵ ، ۴۲۲،۴۱۲،۴۰۳
۹۷
برٹن مسٹر
برہ بنت حراث نیز دیکھئے جو میر یہ
بریدہ رضی اللہ عنہ
بریدہ حصیب رضی اللہ عنہ
بریره
۳۱
بزار
،۳۰۹،۳۰۰،۲۹۵
بسر بن سفیان
۸۱۸،۷۲۸،۵۸۳،۵۷۴،۴۵۹
بسوس
انس بن نضر انصاری
اوس
۵۵۷ بسیس رضی اللہ عنہ
،۳۰۸ ،۲۹۴،۲۹۳،۲۵۷ ، ۲۵۱،۲۵۰،۲۴۵
،۴۰۰،۳۴۰،۳۳۸ ،۳۱۵،۳۱۴،۳۱۳،۳۱۲،۳۱۱
،۵۵۰،۵۴۷،۵۳۰، ۵۲۰ ، ۵۱۷ ، ۴۲۷ ، ۴۰۴ ،۴۰۲
،۶۷۱،۶۶۳،۶۵۹،۶۳۷ ،۶۳۶،۶۳۱،۵۸۹،۵۶۷
بشیر احمد مرزا
بلال بن رباح رضی اللہ عنہ
بلعام
۷۵۵،۶۹۲۶۷۸،۷
بکر بن شداخ رضی اللہ عنہ
۸۰۵،۵۴۸ ،۴۵۶۰ ۴۴۹ ،۴۱۹
۶۹۱
۷۳۹
ง
۶۱
۲۴۹
۵۲۷
۶۱
۱۴۰،۹۶،۶۰
۷۵۵،۷۵۴،۵۲۳،۲۵۶
۸۴۹،۳۲۸،۳۲۷ ،۲۰۳،۶۸
220279
۳۱۰ بکر بن وائل
۹۱۵،۲۴۶
بنانہ
بنو بکر بن وائل
بنوبلی
بنوبنهان
بنوتغلب بن وائل
بنو تمیم
بنو ثعلبہ
بنو ثقیف
بنو جذام
۹۱۴
۸۹۷
۶۹۱
۹۱۴
۳۱
۱۱۶،۱۱۳
۸۵۳
اوس بن ثابت
ایاس
باذان (گورنر یمن)
بازنطین
باعور
بانویه
بخاری امام محمد بن اسماعیل
بحیرا راہب
بدیل بن ورقا
Page 973
۵۹۱،۵۸۸،۵۸۴
۳۸
۸۳۴،۲۵۰،۲۴۹ ،۲۵۵
۱۵۳،۱۴۷ ،۹۷ ،۹۶
۱۵۳،۱۰۰،۹۹
۱۴۶،۱۴۵
۲۶۱،۱۸۲،۱۷۷ ،۹۷
۲۴۳
۱۷۹،۱۵۹،۱۵۸،۱۴۱ ،۹۶
۲۴۳
۲۴۹
۲۵۶
۲۴۳
بنو نج
بنو حارث
بنو حارثہ
بنی حرام
۱۵۳،۱۴۱،۹۶
۲۵۶
بنوعباس
۵۴۹،۲۵۷ | بنوعبدالا شهل
۲۴۷
بنو عبد الدار
بد
بنو عبد الشمس
۲۴۳
بنو حضارمه
بنو حنیفہ
۲۴۳،۵۲، ۷۴۹ بنو عبدالمطلب
بنو خزاعہ ۸۷ تا ۹۵،۸۹، ۹۸، ۸۴۳،۶۲۸، ۸۵۳٬۸۴۸ بنو عبد مناف
۱۴۰ بنو عبس
بنو عدی
بنو عذره
۶۴۷ ، ۵۷۶،۵۷۵،۱۵۲،۱۴۰، ۱۲۱،۱۱۸،۹۶
۸۱،۷۴۷۱
۶۴۷، ۶۶۷ | بنو عمر و بن عوف
بنو عوف
بنو غسان
بنو غطفان ۵۱۱ تا ۶۷۰،۶۴۷،۵۴۳۰۵۳۲،۵۲۶
۵۴۴،۲۱۰،۱۵۸،۱۴۲
۸۱۱،۸۰۸ ،۸۰۷ ،۷۷۱ ،۲۴۳
۲۹۳۸۷،۷۶،۵۳،۵۱
،۶۵۹،۵۹۳،۵۹۰،۵۱۶،۲۹۳
۷۲۶،۷۱۸،۳۲۰،۱۱۳
۲۶۵
۲۵۶،۲۴۹
۸۷۰،۳۶۶،۱۳۹،۱۱۸،۱۰۳
بنو غفار
۲۵۷،۲۵۶ | بنوفزاره
۲۹۷
بنو قحطان
،۶۷۴،۶۷۲۶۷۱،۶۷۰،۶۶۹ ،۶۶۸،۶۶۱،۶۶۰
۱۰۷، ۶۴۷، ۸۰۷ | بنو قریظہ
،۶۸۲،۶۸۰،۶۷۹ ،۶۷۸ ،۶۷۷ ،۶۷۶۶۷۵
،۶۸۹،۶۸۸،۶۸۷ ،۶۸۶،۶۸۵،۶۸۴،۶۸۳
۸۱۷،۸۲۱،۸۰۶ ،۷۴۵ ، ۷۱۲ ،۷۱۱،۶۹۳،۶۹۱۶۹۰
،۵۱۶،۵۰۷،۳۱۲،۲۹۳،۲۹۲،۲۴۵
۸۰۷
۵۴۹،۲۵۷ ،۲۵۶،۲۴۷
،۵۲۶،۵۲۵،۵۲۴،۵۲۳،۵۱۲ ۵۱۱
۷۵۶،۶۴۷،۵۸۴ ۵۸۲،۵۴۳،۵۳۲
خد
بنوج
بنواسد
بنوا سماعیل
بنوا مجمع
بنوامیہ
بنوالدیل
هنوز ریق
بنوزہرہ
بنو ساعده
بنوسالم بن عوف
بنو سعد
بنوسعد بن بکر
بنی سلمہ
بوسلیم
بنوسم
بنو ضبيب
۹۶ | بنو قینقاع
بنو ضمرة
۷۶۹
۳۷۳،۳۷۱
۵۱۸ تا ۸۲۲، ۵۸۷،۵۲۷، ۶۸۵،۶۷۷ تا ۶۸۸
بنو کلب
بنو عامر بن صعصعہ
۵۸۳٬۵۸۲،۲۴۳، بنو کنانہ
۲۴۳۶۸
۳۹۷ ،۳۷۱،۱۸۷ ، ۱۱۸،۱۱۷ ،۵۱
Page 974
،۷۵۱ ،۷۵۰ ،۷۴۹
۹۲۹،۷۵۳،۷۵۲
۵۲
1+4
۹
۲۴۳ ثمامہ بن اثال رئیس بیمامه
۵۷۶ تا ۷۶۲،۵۸۶،۵۸۱،۵۷۸،
۷۶۴۷۶۳، ۷۶۸ | شمود
۹۸، ۱۱۰،۱۰۴۹۹ ، ۲۵۵،۲۴۷، توبه
بنوکنده
بنولحیان
بنو نجار
۳۲۱،۲۹۹۵۲۹۷
ج - چ - ح - خ
،۵۱۲،۳۲۴،۳۱۲،۲۹۳،۲۹۲،۲۴۵
جابر بن عبداللہ بن رمان
۶۵۷،۶۵۲،۶۵۱،۲۵۷ ، ۲۴۷
۵۱۶ ، ۵۲۷ تا ۶۵۹،۶۴۶۰۵۹۴ تا ۶۷۰،
جبار
۵۲۳
۶۷۲ تا ۶۸۰۰۶۷۴ ۶۸۳ تا ۷۳۹،۷۳۴،۶۸۹
بنونوفل
۳۶۶،۱۵۲،۱۱۲،۱۰۰،۹۹ ،۹۵
بنو محارب
بنو مدلج
بنومره
۵۲۳،۲۴۳
جبار بن سلمی
جبر
جبریل علیہ السلام
۵۸۵
۲۲۰،۱۹۷،۱۸۴،۱۸۳ تا ۹۰۰،۲۶۱،۲۲۴
۳۷۳۲۶۷
بنو مخزوم
بنو مصطلق
بنو مطلب
بنو باشم
بنی اسرائیل
بنی عبیده
بیہقی امام
پولوس سینٹ پال
۶۴۷ ،۲۴۳
۱۵۹،۱۵۳،۱۵۲،۱۴۱ ،۱۴۰
۶۴۴،۶۴۳،۶۲۹ ،۶۲۸ ،۶۲۷ ،۶۱۱
،۱۶۰،۱۵۷ ، ۱۴۰ ، ۱۱۸ ، ۱۰۰،۹۹
۱۸۷،۱۸۶،۱۸۲
،۱۵۲،۱۱۸،۱۱۳،۱۰۰،۹۹ ،۹۸ ،۹۵
۱۸۷،۱۸۶،۱۸۲،۱۶۰،۱۵۴ ۱۵۳
۵۰۳۲۹۲،۲۲۲،۱۹۷ ،۸۵،۸۳
۲۴۷
۸۳۵
۷۹
جبلہ بن ایہم رئیس غسان
جبیر بن مطعم
جد بن قیس
جدلیس
جرہم
جرہم الاولی
جرہم الثانیہ
جریح بن مینا ( مقوقس مصر )
جساس
،۲۲۰،۱۹۷ ، ۱۶۹ ،۱۴۴،۱۳۳،۱۰۸
۹۰۰،۵۹۹،۲۶۱،۲۳۲،۲۲۴،۲۲۳۲۲۱
۹۲۸ ،۷۷۹
۵۵۴،۲۵۸
۸۵۵
۵۲
۸۷،۷۶،۵۲
۵۲
۸۷
،۹۱۰،۸۹۶،۷۴۶
۹۲۱ ،۹۲۰ ،۹۱۹ ،۹۱۸ ،۹۱۷ ،۹۱۶
۶۲۶۱
۹۲۶،۲۵۶،۱۷۳۱۴۸
۶۳۰
۴۹۶
۶۴۴،۶۴۳،۴۵۱
۴۵
جعفر بن ابی طالب
جہجاه
جوز فین ملکہ نپولین
جویریہ بنت حارث ام المؤمنین
چلپی کا تب ملا
۳۸،۳۱
۸۰۶
۶۸۰،۶۴۳
تبع اسد شاہ یمن
ترندی امام ابو عیسی محمد بن عیسی
تماضر بنت اصبغ بن عمر
کلبی
ثابت بن قیس انصاری
Page 975
۳۹
،۵۹۴،۱۲۲،۱۱۹
۷۲۶،۷۱۲،۶۱۲
۱۱۹
۲۲۰،۸۹،۸۶
۵۴۲،۵۳۹،۵۳۸
۱۵۷ ،۱۵۴
۳۷۸
۶۴ حسن بن احمد بن یعقوب الہمدانی ابومحمد
۲۴۳،۱۶۳،۱۱۲،۱۰۸،۱۰۴،۱۰۰، ۴۲۱ حسن بن علی رضی اللہ عنہ
حاتم طائی
حارث
حارث بن ابی شمر رئیس غسان و گورنر بصری
۹۲۸ ،۹۰۰
حارث بن ابی ضرار
۶۴۳ حسین بن محمد بن حسن دیار بکری
حارث بن ابی ہالہ
۱۳ حسین بن علی ابن ابی طالب
حارث ( بن اسود )
۴۲۱ حصین بن سلام دیکھئے عبداللہ بن سلام
۴۵۰،۴۰۷ ، ۴۰۳۱۸۸،۱۲۹،۱۲۴
۸۱۱،۲۶
۸۵۲
۸۸
۶۲۶۱
۱۰۶ تا ۱۱۰،۱۰۸
۷۵۶
۵۶۳،۳۷۲
۶۳۹
۳۹
۵۵۰،۳۰۸
۹۳۱،۶۹
،۶۵۹،۶۴۶،۵۹۳۵۱۲،۱۹۱
۸۱۲،۶۸۱،۶۸۰،۶۷۴۶۷۰
۸۳۱
۳۱۰
حارثہ بن نغلبه
حارث بن حرب
حارث بن عامر بن نوفل
حارث بن عبد الطلب
حارث بن قیس
۲۹۳
حطیم
۲۵۸ | حفصہ بنت عمر
۵۷۹ حکم بن ابی العاص
۱۰۰ ۱۰۴ حکم بن کیان رضی اللہ عنہ
۱۵۴۹۶
حکیم بن حزام
حارث بن مسلم بن حارث
حارثہ
حارثہ بن نعمان انصاری
۳۵۲،۳۵۰ | حلبی علامه
۵۱۶،۱۲۵ | حلیس بن علقمه
۵۱۵ | حلیل بن حبشیه خزاعی
حاطب بن ابی بلتعہ
۹۱۶، ۹۲۰،۹۱۷ | حلیلہ بنت مره
حاکم
۲۹۶
حباب بن عبداللہ بن ابی دیکھئے عبداللہ بن
حلیمه (مزنی)
ابی حباب بن منذ ررضی اللہ عنہ ۵۴۷،۵۴۵،۴۰۴ | حمزه بن عبد المطلب
حی بنت حلیل بن حاشیه خزائی
حجاج بن یوسف
حذیفہ بن یمان
حرام بن ملحان
حرب بن امیه
حرث بن ابی ضرار
۸۸ حمنہ بنت جحش
۴۷۱،۹۰ حمیر قبیلہ
۶۷۰،۴۰۶،۳۶۲،۳۱۰
۵۸۴،۵۸۳
حنظلہ بن ابو عامر
حور
۱۰۰ ، ۱۱۸ | حیی بن اخطب
۶۲۸
حسان بن ثابت ۶۴۰،۶۳۹،۲۰۶ ،۹۱۹،۶۶۶ خارجه بن حسیل
۴۵۷، ۴۷۱ | خارجہ بن زید
حسن بصری
Page 976
۲۱۱،۲۱۰
۵۸۶،۵۸۴،۵۸۳۵۸۲
۲۴۹
۶۸
۴۵۰
121820
۵۴۸
۲۵۶،۲۴۹
۶۳۳
۶۹
۵۸۲ تا ۵۸۶،۵۸۴
ΥΛΙ
22.۶۹۳
۶۹۱
،۳۹۹،۱۶۵،۱۲۱
۵۲۴۴۱۷
۱۵۴
۶۸۳۶۸۲
11
خالد بن ولید
۵۶۰،۵۵۳،۵۴۵ ،۴۱۹ ،۳۲۱
دوس
خباب بن الارت ۱۶۳۱۵۹،۱۴۲، ۵۹۹،۲۷۵،۱۷۷ | ذکوان
خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ
۵۷۹ ذکوان بن عبد قیس
۱۲۱،۷۰، ذوالکلاع خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین خدیجہ الکبری
ذوالکلاع الحمیری
۱۲۴،۱۲۲، ۱۲۶ ، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۴،۱۳۲،۱۳۱ تا ۱۳۷،
خراش بن امیه
خزاعه
،۱۹۷ ، ۱۹۵،۱۹۴،۱۹۲،۱۸۸ ،۱۶۳،۱۴۷ ،۱۴۲،۱۳۹
۷۶۲۷۵۷ ،۶۲۳ ،۵۱۴،۵۰۳ ، ۴۷۹ ،۴۱۸ ،۲۰۰
۸۵۴،۸۵۳
رازی فخر الدین
رافع بن خدیج
رافع بن مالک
۹۵،۸۹،۸۸،۸۷، ۵۶۸،۹۸، رام چندر جی
ربع
۸۵۳٬۸۴۸ ،۸۴۳،۶۲۸
،۲۴۹،۲۴۷ ،۲۴۶ ، ۲۴۵ ،۹۸ ،۶۸ ،۵۳،۵۱
رعل
رفاعه
رفاعہ بن زید
۹۱۶۹۱۵،۹۱۲۹۱۱
خزرج
۲۵۲۲۵۰ ۲۵۳ ۲۵۵۰ تا ۳۰۰،۲۹۴۲۹۳،۲۵۸
خسرو پرویز بن ہرمز
خطیب بغدادی
٣٣
خلاد
۶۷۵
خنساء عرب شاعرہ
خیس بن حذافہ
خولہ بنت حکیم
۵۳۹،۵۳۸
۴۸۸،۴۷۹،۱۹۷
خویلد بن اسد
۱۲۱
د.ذر.ز
دارقطنی امام
داؤد علیہ السلام
دبلوم مفسر تورات
رفیدہ رضی اللہ عنہا
رقیہ بنت محمد رسول الله الله
رکانہ بن یزید
رملہ دیکھئے ام حبیبہ ام المؤمنین
ریحانه
زبیر بن ابوامیه
۲۹ زبیر بن با طیا
۵۰۳،۱۹۶،۷۴ | زبیر بن عبدالمطلب
۸۴ زبیر بن العوام
دحیہ بن خلفیہ الکلمی ۷۷۱،۷۷۰، ۹۰۲۹۰۰، ۹۰۷، ۹۰۸
۱۵۲
۶۸۲۶۸۰
۱۱۸
،۱۷۴،۱۶۵،۱۵۸،۱۳۹،۷
۶۵۹،۵۹۸،۵۶۳،۴۰۳،۳۲۰،۲۶۸
۷۴۲
۹۳۰،۸۳۵،۸۱۱ ، ۶۲۱ ،۴۸۱،۴۲،۳۴
زرتشت
زرقانی علامہ
۵۲۳
۴۲۴
دعثور بن حارث
دوانی
Page 977
س ش ص ض.ط
۸۴،۸۳،۷۸ ،۷۴ ۷۳
۹۹۱،۸۹۷
۵۰۷
۵۰۷
۵۰۷،۵۰۴
۴۵۷ ،۴۵۲
۵۱
المهم
۷۹۳
،۲۶۸،۲۶۷ ،۲۶۵
۴۰۷ ،۳۹۷ ،۳۳۷
۶۱
ساره
ساسان
سالم بن عبداللہ
سالم بن عمر و
سالم بن عمیر
سالم بن معقل مولی ابی حذیفہ
،۳۷۳،۳۱۷،۱۸۷ ،۱۴۵،۱۳۹
سائب بن عثمان بن مظعون
،۴۲۳،۴۰۳،۴۰۰،۳۷۸ ،۳۷۵
۸۶۴،۵۶۲۵۵۸،۵۵۷ ، ۴۷۳
۲۵۷
سبا
سیر نگر
سٹالن مارشل
سراقہ بن مالک بن جعشم
سعد
سعد بن ابی وقاص
سعد بن خیمه
۱۲
۴۸۸،۴۰۳،۱۹۷ ،۱۸۸
۱۵۹
۶۳۱
زمعہ بن اسود
زنیرہ رضی اللہ عنہ
زید بن ارقم
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ۲۷۴۷، ۵۹۹٬۵۹۸،۵۹۷
۵۹۹،۵۹۸،۵۹۷۷
الدح
زید بن ثابت انصاری
زید بن الخطاب
زید بن دشنہ رضی اللہ عنہ
۵۸۱،۵۷۹
،۴۱۷ ،۴۱۶،۳۷۳،۲۰۴،۱۲۴،۱۱۲
زید بن حارثہ
،۶۲۱،۶۲۰،۶۱۲،۶۱۱،۵۳۸ ، ۴۹۹،۴۵۶۰ ۴۵۲۰ ۴۵۱
،۷۷۹ ،۷۷۱ ،۷۶۹ ،۷۶۸ ،۷۵۷،۷۵۶،۶۲۸
۸۱۰،۸۰۹،۸۰۸۰۷۸۴
زید بن عمرو بن نفیل
زین الدین عبدالرحیم بن الحسين العراقی
زینب رضی اللہ عنہا
۱۴۱
۲۸،۱۳
،۶۱۳،۴۹۹،۱۲۲،۱۲۱
۹۳۱ ،۷۶۱،۶۲۶،۶۲۱،۶۲۰۶۱۴
زینب دیکھئے ام رومان
زینب بنت جحش ام المؤمنين
،۴۹۹،۴۵۲،۱۴۱
۶۳۹،۶۳۸،۶۲۳،۶۱۹ ،۶۱۸ ،۶۱۱
زینب بنت خزیمہ
۵۹۴
زینب بنت رسول اللہ ۴۵۲،۱۴۱، ۶۱۲،۶۱۱،۴۹۹،
سعد بن الربیع رضی اللہ عنہ رئیس انصار ۵۷۱،۵۶۴۲۵۶
،۲۷۹،۲۷۰،۲۵۸ ،۲۵۶
۶۶۵،۶۵۹،۶۳۷ ،۶۰۹ ،۴۰۰ ،۳۹۹،۳۰۰
۲۵۰ تا ۲۵۵،۲۵۲،
سعد بن عبادہ رئیس خزرج
سعد بن معاذ رئیس اوس
،۶۶۵،۶۶۳۶۵۹،۶۳۷ ، ۵۶۷ ، ۴۰۴ ،۴۰۲،۳۷۰
17h377 V7LVL'16' 777
۴۰۰،۳۹۶،۱۴۲۶۹
۵۸۰
سعید بن زید رضی اللہ عنہ
سعید بن عامر
،۶۲۲،۶۲۱،۶۲۰،۶۱۹ ،۶۱۸ ،۶۱۵ ،۶۱۴،۶۱۳
۷۶۱،۷۵۸،۶۳۹،۶۳۸ ،۶۲۶،۶۲۵،۶۲۳
۶۱۲،۵۸۹،۳۶،۳۵
VVI
زہری امام
زہیر
زہیر بن ابی امید
زیاد بن سکن
Page 978
سعید بن منصور
۱۳
۳۳ سودة بنت زمع ام المؤمنین
ام
،۱۹۹ ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۹۶
۵۷۸،۵۷۷،۵۷۶
۶۴۷
سوید بن صامت
۴۸۹،۴۸۸،۳۰۳،۲۰۰
۴۸۹،۴۸۸ ،۲۰۰،۱۹۸ ،۱۹۷
۴۴۲
۷۴۱
،۸۵۲،۴۱۹ ،۴۱۵،۴۰۳
۸۷۲،۸۶۴،۸۵۹٬۸۵۸۰۸۵۷
۸۱۱،۵۰۶
سفیان بن خالد
سفیان بن عبد شمس
سکران بن عمر و
۱۹۷ سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ
سلام بن ابی الحقیق ابو رافع ۸۳۰،۸۱۲،۶۴۶،۵۹۳ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ
سلام بن مشکم
سلطان بن احمد طبرانی
سلمہ بن اسلم
۵۸۸،۵۱۳،۵۱۲ | سہیل بن عمر و
۳۲
۸۳۵
۸۱۱،۸۰۸ ،۶۹۶
سهیلی امام
سیتاجی
۵۷۵ سیرین (قبطیه )
۹۸ شافعی امام محمد بن ادریس
۲۹۷ شیلی نعمانی
۴۴۸، ۴۴۹ شبیہ بن ہاشم دیکھئے عبدالمطلب
سلمہ بن اکوع
سلمه بن خویلد
سلمی زوجه باشم
سالمی والدہ عبد المطلب
سلمان رضی اللہ عنہ
سلمان فارسی
سلیمان علیہ السلام
سلیمان بن اشعب ابو داؤد
سلیط بن عمر و قریشی رضی اللہ عنہ
سمرہ بن جندب
سموئل بن عادیه
سمیہ رضی اللہ عنہ
ستان
سواع
سوٹر.اے مصنف
۶۴۸،۳۱۰،۳۰۸ ،۳۰۷
۶۴۷،۶۴۶،۵۲۳،۵۲
شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ
شرجیل بن حسنہ
۵۰۳،۱۹۷،۷۴ شعبه بن الحجاج
۳۱ شعی رضی اللہ عنہ
۹۲۹ شعیب علیہ السلام
۵۴۸ | شفاء بنت عبداللہ
۶۴
۱۶۰،۱۵۹،۱۴۸
Text.Canon of new Testament
۶۳۰
شیبہ بن ربیعہ
مینجین
۶۸ شیر علی مولوی بے اے
شیرویہ بن خسر و
شیما ( حضرت حلیمہ کی بیٹی )
۱۸۴ شیما بنت حارث رضی اللہ عنہ
۶۳۳
۹۱۹
۳۲
۳۸۵،۳۸۴ ،۲۸۸
۹۲۸
۲۹
۱۷
۵۲
۵۴۲
،۴۰۸ ،۴۰۳،۲۰۵،۱۸۰،۱۵۳
۴۲۲،۴۲۱ ،۴۱۲
۵۴۷
۲۸۹
۹۱۵
۱۰۷
11 +
Page 979
۳۹۶
۵۲
عاتکہ بنت عبدالمطلب
عاد
عاص بن وائل
ع غ
عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ
عاصم بن عدی
۳۲۱،۲۶۵،۱۷۹،۱۵۹،۱۵۴
۵۸۱،۵۷۸
۴۰۱
۳۵۱
۴۰۸
۵۸۸،۵۸۵،۵۸۴،۵۸۳
۵۸۵،۲۶۸،۲۶۶،۱۴۲
۸۴۳،۲۵۵
،۸۹،۱۹ ،۱۵ ،۹
عاصم بن کلیب
عامر حضرمی
عامر بن طفیل
عامر بن فهيره
عائذ بن عمرو
عائشہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر
،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۹۶ ۱۹۵ ، ۱۹۱ ، ۱۷ ،۴ ، ۱۴۰ ،۱۳۰،۱۲۷
،۲۷۴،۲۷۲،۲۶۲،۲۶۱،۲۵۵ ،۲۱۵ ،۲۰۶،۲۰۰،۱۹۹
،۴۸۲،۴۸۱،۴۸۰ ، ۴۷۹ ، ۴۵۰ ، ۴۴۸،۳۲۰،۳۰۳
۱۴
۲۲۰،۵۲
،۳۳۴،۱۵۸،۹۶
۵۸۱،۵۷۹،۵۴۵،۵۲۶،۴۲۵
۶۴۰،۶۳۴
۹۲۰
۶۶۶،۵۶۳۱۳۹
۵۵۳
۶۹۱
۴۴۹،۱۵۹،۱۴۹،۱۴۸
۲۷۹
۳۹۸،۳۹۶
۶۰۷
۱۲۱
۳۷،۳۴
۵۲
،۵۳۹،۴۸۹،۴۸۸ ، ۴۸ ۷ ، ۴۸۶ ، ۴۸۵ ، ۴۸۴ ، ۲۴۸۳
۵۵۴،۴۰۳
،۶۲۳،۶۲۲،۶۱۹،۶۱۵،۶۱۱،۵۹۷،۵۵۵،۵۴۲
۲۷۹
،۶۴۳،۶۴۰،۶۳۹،۶۳۸ ،۶۳۷ ،۶۳۶،۶۳۳
۵۵۹،۵۵۳،۵۵۱،۵۵۰
۹۳۱،۷۲۲،۶۹۶
۹۶
۸۴۳،۲۵۵
۲۵۶،۲۴۹
عباد بن بشر
عبادہ بن صامت
عابدہ بن الولید
عباس بن عبادہ بن نضلہ انصاری
عباس بن عبد المطلب
۴۳۵
۲۵۴۲۴۹
،۲۵۸،۱۵۸،۱۴۲،۹۵
۵۴۴،۴۱۸ ،۴۱۷ ، ۴۱۵ ،۴۰۹ ،۳۹۲
۵۱۸
۴۰۰،۳۹۶،۱۴۰
۶۴۷،۵۷۵
۶۸
۱۲۱
صالح علیہ السلام
صفوان بن امیہ بن خلف
صفوان بن معطل
صفیه ام المؤمنین
صفیہ بنت عبدالمطلب
صواب
صور
صہیب بن سنان رومی
ضماد بن ثعلبه از دی
ضمضم
طالب بن ابی طالب
طاہر بن محمد
طبری ابو جعفر محمد بن جریر
طرفه عرب شاعر
طعیمہ بن عدی
طفیل بن عمر والدوسی
طلحہ رضی اللہ عنہ
طلحہ بن ابی طلحہ
طلحہ بن براء
طلحہ بن عبیداللہ
طلیحہ بن خویلد
طی
طبیب بن محمد
Page 980
۵۲۴
۸۴۳،۵۴۷ ، ۴۰۱
۸۳۳٬۸۳۲،۵۷۷
۵۵۳،۵۴۹
۵۹۴۵۶۴،۳۷۶،۳۷۴
۱۴۸،۱۱۸،۱۰۰
۱۰۷
۹۱۳
۵۵۰،۱۷۲
۵۹۸
۶۰۶
۵۵۷
۱۵
عباس بن نضله
عبدالبر
عبدالدار
عبد شمس
عبد قصی
۲۴۹ | عبدالله بن عثمان بن عفان
۵۰۶ عبد الله بن ام مکتوم
۹۷ عبد اللہ بن انیس انصاری
۱۶۱،۹۷ عبداللہ بن جبیر
۹۷ عبداللہ بن جحش
عبدالمطلب بن ہاشم ۸۸، ۹۸ تا ۱۱۱،۱۰۵ تا ۱۱۳، عبداللہ بن جدعان قرشی تیمی
۱۹۳،۱۴۰،۱۱۸، ۲۴۷ ، ۲۹۷، ۶۰۷ | عبداللہ بن حارث (حلیمہ کا بیٹا )
عبد مناف
عبدالرحمن بن ابی بکر
۹۹٬۹۷ | عبدالله بن حذافہ سہمی
۹۳۱ | عبدالله بن ربیعہ
عبدالرحمن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی ۳۴ عبدالله بن سعد ابی سرح
عبدالرحمن بن ابی حاتم الرازی
عبدالرحمن بن زبیر بن باطیا
عبدالرحمن بن عبد اللہ سمیلی
عبدالرحمن بن عوف
۲۹ عبد اللہ بن سلام ( حصین بن سلام )
۶۸۲ | عبداللہ بن شہاب
۴۴ عبد اللہ بن طارق
۱۳۹ ۱۶۴ ۲۸۱،۱۶۵ | عبدالله بن رواحہ
،۴۶۵،۴۵۰،۴۱۳،۴۱۲ ،۴۱۰ ،۳۳۵،۳۱۰
۸۰۴،۷۱۸،۵۶۶ تا ۶ ۸۶۴،۸۰ | عبد اللہ بن زبیر
۳۳ عبدالله بن عامر اسلمی
۵۷۹
،۷۳۸،۶۴۹،۵۹۸ ،۳۰۱
۸۳۳٬۸۳۲،۸۳۱،۸۳۰
۷۲۶،۷۱۸،۳۲۰
۶۲۰
۹۰۲،۵۹۸
۳۲
۶۳۲،۵۹۵
۱۰۴۱۰۳،۱۰۱،۸۱
۸۱۳ تا ۸۱۶
۵۴۸،۴۷۱،۴۵۰
۲۳
۲۳
عبدالرزاق
عبد الرؤوف المناوى
عبدالعزی
عبدالغنی بن عبد الواحد المقدسی
۲۹ عبداللہ بن عباس
۹۷ عبداللہ بن عبد الرحمن الدار می
۲۹ عبد اللہ بن عبد اللہ ابی ابن سلول
عبداللہ بن ابی ابن سلول ۲۹۴،۲۵۸، ۳۱۴،۳۰۸، ۳۳۸ | عبدالله بن عبد الطلب
۵۴۶،۵۲۰،۴۲۷، ۶۳۰،۶۲۶،۶۲۲،۵۹۱،۵۴۸ عبد اللہ بن عتیک انصاری
۳۰۱ عبد اللہ بن عمر
۱۲۰ عبد اللہ بن عمرو
عبداللہ بن ابی بکر
عبد اللہ بن ابی الحمساء رضی اللہ عنہ
عبد اللہ بن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ۱۲۹، ۱۳۸ | عبدالله بن عمرو بن العاصی
عبد اللہ بن اریقط
۲۶۵ عبد اللہ بن قمه
Page 981
۵۲۲،۴۷۳،۳۷۳،۱۶۵،۱۴۱
۷۴۲
۴۰۱
۴۸۷
۸۴۹
۸۳۵
۵۶۲،۳۳۱
۵۰۶،۵۰۴ تا ۵۱۰
۵۸۶،۵۸۴
۵۷۸
۴۷۱،۴۵۷ ،۴۵۲
۶۸۲
،۱۹۶،۱۶۲۱۵۳،۱۴۱
۸۶۸ ،۴۲۲،۴۱۲۰۴۱۵،۴۰۳
۵۸۰
۲۴۹،۲۴۷
۶۰۷ ،۱۲۶
۴۲۱
17
۴۵۷ | عثمان بن مظعون
عداس
عدنان
۴۰،۲۹
۱۲۱
عبداللہ بن مبارک
عبداللہ بن محمد ابو احمد المعروف بابن عدی
عبد اللہ بن محمد
عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ
عبداللہ بن منجره
عبداللہ بن مسعود ہذیلی ۱۴۱، ۴۱۲،۲۷۹،۱۹۰،۱۵۸ | عدی رضی اللہ عنہ
۳۸ | عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ
۹۳۱
عروہ بن مسعود
عبدالمالک بن ہشام
۳۶
عرینہ
عبدالمالک بن مروان
عبدیالیل رئیس طائف
۹۰ | عزی (بت)
۲۰۴
عصماء
عصر
عضل
۹۲۷ ،۱۴۱
۹۶۶،۴۰۸،۳۷۱ ،۳۶۶
۴۰۸ عطاء بن ابی رباح
۴۰۳٬۲۰۵،۱۸۰،۶۳ | عطیه قرطی
۱۲۲ عقبه ابی معیط رئیس قریش
٣٣،٢٩
۷۵۴،۷۵۳
،۵۴۵،۴۱۱ ،۳۷۱،۳۶۶،۳۳۰
۸۵۳٬۸۸۴،۵۷۰، ۵۶۱،۵۵۳،۵۵۰
۴۵۷
۸۳۵
عقبہ بن حارث
۵۵۷
۸۷۰
۲۰۴،۱۸۰،۱۵۵،۱۵۳،۱۴۱، عقبہ بن عامر
۳۷۷، ۴۰۷، ۶۲۴،۴۲۱ | عقیل بن ابی طالب
۳۷۵،۳۷۱،۳۶۶ | عقیل ( بن اسود )
۳۱۰،۱۸ عقیلی حافظ
۵۵۱ عکاشہ بن محصن
عبید اللہ بن جحش
عبیدہ بن حارث مطلبی
عبیده بن مطلب
عقبه
عقبہ بن ابی لہب
عتبہ بن ابی وقاص
عتبہ بن اسید ثقفی ابو بصیر
عتبہ بن ربیعہ
عتبہ بن غزوان
عتبان بن مالک انصاری
عثمان (برادر طلحه )
عثمان بن حویرث
عثمان بن طلحه
۷۰ عکرمہ بن ابی جہل
۹۶
عثمان بن عبد الرحمن ابو عمر والمعروف بابن الصلاح ۲۸ عکرمہ مولی ابن عباس
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
،۳۹۹،۱۶۵،۱۲۲
عکل
۴۵۰ ۸۶۸،۸۵۴،۵۹۹،۵۶۹،۵۵۶،۵۳۸،۵۲۴۷ | علقمه عرب شاعر
Page 982
لا
،۶۲۸ ،۶۰۰،۵۹۹،۵۹۸ ،۵۸۱،۵۸۰، ۵۷۴،۵۷۳
،۷۱۸،۷۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ، ۷۰۹ ،۶۳۱،۶۳۰،۶۲۹
،۷۵۶،۷۵۵،۷۴۰ ،۷۳۹،۷۳۸ ،۷۳۷،۷۳۵
،۸۶۹۰۸۶۷ ،۸۶۴،۸۶۲،۸۵۴،۷۷۹ ،۷۷۸
۹۲۹ ،۹۱۱،۹۰۹ ،۸۹۵،۸۹۳٬۸۷۰
۴
۲۴۹،۲۴۷
۲۴۹
،۱۳۰،۱۲۶،۱۲۵،۱۲۲،۲۴
عشرہ عرب شاعر
عوف بن حارث
عویم بن ساعدہ
علی بن ابی طالب
،۱۵۳،۱۴۹،۱۴۸ ، ۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴ ۱۴۰ ،۱۳۹،۱۳۸
۱۲۱
،۵۸۷،۵۸۵،۵۸۴
۹۲۳٬۸۳۵،۵۸۸
۵۸۸
۴۵۱
۸۷
۳۹۴
۶۶۲،۵۴۵،۳۲۱،۱۷۳،۱۷۲،۲۳
۶۶۲
۲۴۹
۱۲۱۶۴،۴
۸۸
۱۷۸،۱۵۳
۶۴
۵۵۴
۴۰۰
۵۰۶،۵۰۴
۴۲۶،۴۰۶
۴۱۴
۲۴۲ ،۹،۲۵۵ ۲۵ ،۲۶۳، ۴۰۸ ، ۴۱۰ ، ۴۵۹،۴۱۵ | عمرو بن اسد
۵۵۲٬۵۵۱،۵۵۰،۵۴۷،۵۴۲،۵۳۱،۵۱۵،۵۱۴ | عمرو بن امیہ ضمری
۸۰۷ ،۸۰۶،۷۷۰ ، ۶۷۵ ، ۶۶۴ ۶۰۷ ، ۵۶۰۰۵۵۹
علی بن برہان الدین الحلمی
۴۴۰۲۶ | عمرو بن جحاش
علی بن حسین امام زین العابدین
۶۱۲ عمرو بن الحارث
علی بن حسین مسعودی ابوالحسن
۳۸ | عمرو بن الحرث
علی بن عبد اللہ بن جعفر المعروف بابن المدینی ۴۱ عمرو بن الحضر می
علی بن محمد الدار قطنی
۴۱،۳۲
عمر و بن العاص
علی بن محمد بن عبدالکریم المعروف ابن اثیر ۳۰ عمر و بن عبدود
علی بن محمد سلطان القاری المشہو رملاعلی القاری ۱۳، ۲۸ | عمرو بن عوف
عمر و بن كلثوم
۴۱۹،۳۱۰،۱۶۰،۱۴۸
عمرو بن لحی
عمرو بن معاو
۲۹۲ عمرو بن ہشام (ابو جہل)
۹۶،۸۵،۶۹،۱۹،۱۸،۸،۷، | عمرو بن ہند
(مصنف موضوعات کبیر)
عمار بن یاسر
عماره بن ولید
عمالیق
عمر بن الخطاب
۱۴۲،۱۴۱،۱۴۰،۱۳۹،۱۲۹، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۸، | عمره بنت علقمه
۱۷۶،۱۷۵،۱۵۹، ۱۷۷ ، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۶،۱۸۰، عمیرہ بن ابی وقاص
۲۵۶،۱۹۱، ۲۶۸، ۲۷۱، ۲۷۵، ۳۰۴،۳۰۳،۲۹۶، عمیر بن عدی
۴۱۳،۳۹۹،۳۶۲،۳۲۵ ، ۴۱۷، ۴۲۵،۴۲۳،۴۱۹، عمیر بن وہب
۴۲۶ ، ۴۳۸، ۶ ۴۴ ، ۴۵۲،۴۴۸، ۵۰۴،۴۷۱،۴۵۶، عمیر وقاص
۵۳۹،۵۳۸،۵۱۴، ۵۶۱،۵۶۰،۵۵۷،۵۴۷ | عیاض قاضی
Page 983
۱۸
عیسی بن مریم ۲۲۳،۲۲۱، ۲۲۵ ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۵۵،۲۲۸، | قریش (قبیله )
۹۲۵،۹۲۴ ،۹۱۸ ،۹۱۷ ،۸۹۷ ،۸۹۲۶۳۳،۲۷۹
عینی علامه
عیینہ بن حصن فزاری
غزالی امام
غزیه
غشمیر
غطفان
۴۸۱،۱۶۹
۶۴۷
۱۹۲
۶۴
،۸۰،۷۸ ،۷۷ ،۶۸،۵۹،۵۵
۸۷ تا ۹۵،۹۳ تا ۱۱۳،۱۰۳ ، ۱۱۷، ۱۳۰،۱۲۹،۱۲۲،۱۱۸،
۱۳۱، ۱۳۸، ۱۴۰ تا ۱۴۵ ، ۱۴۷ تا ۱۶۳ ۱۶۵ تا ۱۷۶
۱۷۹ تا ۱۹۳،۱۸۹ تا ۲۱۲،۲۱۱،۲۱۰،۲۰۳،۱۹۸،۱۹۶،
۲۴۱ تا ۲۴۴ ، ۲۴۶، ۲۵۲،۲۴۸ ۲۵۸ تا ۲۷۰،۲۶۷،
۲۷۶،۲۷۱، ۲۷۸ تا ۳۱۲،۲۸۲ ، ۳۱۴ تا ۳۱۹،۳۱۸،۳۱۶،
۳۳۱،۳۲۲ ،۳۳۴،۳۳۳ تا ۳۶۲،۳۵۵،۳۵۴،۳۴۰،
۵۲۳،۵۱۲،۵۱۱ تا ۵۴۳،۵۳۲٬۵۲۶،
۳۶۵ تا ۳۸۴،۳۷۸ تا ۳۹۹، ۴۰۱ تا ۴۱۳،۴۱۲،۴۱۰،
۴۱۵، ۴۱۸ تا ۴۲۳ ، ۴۲۶،۴۲۵ ، ۴۲۸، ۵۱۲،۵۱۱،۴۴۹، ۶۴۶،۵۸۲، ۶۴۷ ، ۶۶۵، ۶۶۷ تا ۸۱۳٬۸۱۲،۶۷۰
غفار
غلام احمد قادیانی بانی سلسلہ احمدیہ
غیلان بن سلمه سقفی
فق
۱۴۲
۸۴۷ ،۴۱۵
۴۹۸
فاطمہ فاطمۃ الزہراء بنت حضرت محمد مه ۱۲۱ تا ۱۲۲، ۵۱۱،
۵۱۴ تا ۵۱۶ ۵۲۴ ،۵۴۲، ۶۱ ۷۷۸،۷۶۲،۵۹۴،۵
فاطمہ بنت اسد
فاطمہ بنت الخطاب
فاطمہ بنت قیس
۶۰۷ ،۶۰۶
۱۴۲
۱۷
۵۲۳،۵۱۷،۵۱۳ تا ۵۴۴،۵۴۳،۵۳۲،۵۲۸ تا ۵۴۶
۵۵۰،۵۴۹ تا ۵۶۷۰۵۶۴ تا ۵۷۸۰۵۷۶۰۵۷۰ تا
۶۱۰،۵۹۶،۵۹۵،۵۸۷،۵۸۲ ،۶۲۶تا۶۴۶،۶۲۹،
۶۴۷، ۶۶۲۰۶۴۸ ۶۶۸۰۶۶۴۰ تا ۶۹۳،۶۸۶،۶۷۲،
۷۲۶ تا ۷۳۰ ۴۰۰ ۷ ، ۷۴۷، ۷۵۷،۷۵۵،۷۵۲،۷۵۱،
۸۴۸۰۸۴۴،۸۴۳٬۸۴۱،۸۳۵،۸۳۳،۷۸۴تا
۸۵۷،۸۵۵ تا ۸۶۶۰۸۶۳٬۸۵۹، ۸۷۰،۸۶۷،
۸۷۱ تا ۸۸۹،۸۸۴،۸۸۲،۸۸۰،۸۷۶۰۸۷۴،
۹۳۰،۹۰۳۹۰۲۸۹۹
۸۳۵،۴۸۱،۱۷
۷۲۹،۵۵۰،۹۵،۸۸
۹۸
۲۴۹،۲۴۷
۷۳
۸۰۸
۷۴۱
قس بن ساعدہ
قسطلانی علامه
قصی بن کلاب
فضلہ بن باشم
قطبه بن عامر
قطور ا حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام
تیں
قیس بن سعد
۵۲۷
۹۱۷ ،۹۰۱ ،۷۷۸ ،۷۲۷ ، ۲۱
۶۶
۱۴۰،۹۵،۹۲،۸۸
۵۷۸،۱۷۴
۱۷۲
۹۱۸ ،۹۱۷ ،۹۱۶
۷۴۸
فرات
فرعون
فطیون رئیس یہود مدینہ
فہر بن مالک
قاره
قاسم بن محمد
قبط
قرطا
Page 984
۷۴۲
۲۴۳،۱۶۸،۱۵۸،۶۸
م
۱۵۹
۴۳۸ ،۳۵،۳۲،۳۱
۲۴۹
۱۵۴
۹۲
۹۲۱
۱۹
۱۱۷ ۱۱۸ گوتم بدھ
لات بت
لم
،۵۰۴،۵۰۳،۳۷۶،۳۷۵
قیس عیلان
قیصر روم
،۸۷۵،۸۷۴،۷۷۱ ،۷۰ ،۶۹ ،۷۶۵
،۹۰۴ ،۹۰۳،۹۰۲،۹۰۰،۸۹۹ ،۸۹۸ ،۸۹۷ ،۸۹۶
۹۲۸ ،۹۱۶ ۰۹۱۵ ،۹۱۳ ،۹۱۲،۹۱۱ ،۹۰۹ ،۹۰۸ ،۹۰۷ ،۹۰۵
لبيد
۴۲۰،۸۷،۷۹
۳۷۳،۳۷۲
لبینہ رضی اللہ عنہ
مالک بن انس امام
مالک بن تیہان ابوالبیشم
۷۶۵،۵۰۳٬۱۵۰ | مالک بن طلاطله
قیدار بن اسماعیل
ک میگ
کرز بن جابر فہری
کرشن جی مہاراج
۶۵۱،۲۸۱،۲۶۸،۱۰۵ ، مالک بن نضر کسری ابن هرمز شهنشاه ایران
۹۰۰،۸۹۹،۸۹۸،۸۹۷،۸۹۶،۸۸۹،۸۵۱، مارگولیتھ پروفیسر
۵۲۲،۵۲۱،۵۰۹،۵۰۸، ۵۲۵ تا ۶۸۹،۵۲۷
۹۲۰،۹۱۹،۱۲۱
۷۹۳
۴۵۷ ،۴۵۲
۳۷۲
۹۱۳۲۴۱
مارگولیس
۹۲۷ ،۹۱۶،۹۱۵ ،۹۱۴ ،۹۱۳ ، ۹۱۲ ، ۹۱۱۰۹۰۱
۱۲۵
کعب ( زید کے چچا )
۶۸۰۰۶۷۵،۶۵۹ ، ۶۸۱ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کعب بن اسد رئیس قریظہ
۵۲۹،۵۲۷،۵۰۹،۵۰۶، | مالوٹو و مسٹر کعب بن اشرف
۷۵۵،۶۸۶،۵۹۱،۵۳۷،۵۳۵،۵۳۱، | مجاہد بن جبیر
۸۱۲، ۸۱۵ تا ۸۱۷ مجددی بن عمر والجبنی
کعب بن زہیر
کعب بن زید
۶۰ مجوس
۵۸۵،۵۸۴ | محمد صلی اللہ علیہ وسلم
،۷۷،۷۴،۷۰ ، ۱۰،۹،۶،۵،۴
،۱۴۲،۱۳۹،۱۳۵،۱۳۱ ،۱۳۰ ،۱۲۳،۱۰۸ ، ۱۰۵ ،۱۰۴
،۱۷۶،۱۶۲،۱۶۱،۱۵۸ ،۱۵۷ ، ۱۵۶،۱۴۶ ۱۴۵ ۱۴۴
،۱۹۳، ۱۹۲،۱۸۷ ، ۱۸۵،۱۸۴،۱۸۳،۱۸۲،۱۷۸،۱۷۷
۲۴۲،۲۲۷ ،۲۲۴ ۲۲۰،۲۱۹ ،۲۱۰ ،۲۰۶ ،۱۹۶ ۱۹۴
،۲۶۷،۲۶۳۲۶۰،۲۵۸ ،۲۵۴ ،۲۵۳،۲۴۸،۲۴۶
،۳۳۶،۳۳۱،۳۱۶،۳۱۵،۳۱۴،۳۰۷ ،۳۰۳۲۹۸
،۵۰۳،۴۲۲،۴۲۱،۴۱۹ ،۴۱۰،۳۹۶،۳۴۳،۳۳۸
۶۸۲
۳۵۳
۳۲۰،۲۹۵
บ
۶۴۶،۵۹۳
۷۴۲
۲۳۰
Page 985
،۵۵۶،۵۵۲،۵۵۰، ۵۴۸،۵۳۰،۵۲۸،۵۱۷،۵۰۴
۷۴۹،۵۹۲،۵۸۹، ۷۵۴،۷۵۰ تا ۷۵۶
۶۱۹،۵۸۹،۵۸۸،۵۶۷،۵۶۰،۵۵۹، ۶۴۹ ، محمد بن یزید بن ماجه قزوینی
۶۶۸،۶۶۳،۶۶۲،۶۵۹ ،۶۷۶، ۶۸۵،۶۷۷ ، محمد مختار پاشا مصری
۴۳۸،۸۳۲ ،۸۵۹٬۸۵۲،۸۵۱،۸۵۰،۸۴۷، | محمود بن الربیع
۸۷۴، ۶٬۹۰۲،۸۹۹ ۹۲۴٬۹۰ محمود پاشا مصری
انادعوة ابراهيم
آپ کی آمد سے عربوں میں انقلاب
آپ کا زمانہ ۵۷۰ ء سے ۶۳۲ ء تک قرار دیا گیا ہے
محمد ادرلیس ابو حاتم
محمد اسحاق
محمد بن احمد الذہبی ابو عبد اللہ
محمد بن ادریس الشافعی
محمد بن اسماعیل بخاری
محمد بن بشار بندار
محمد بن جریر الطبری ابو جعفر
محمد بن سعد
محمد بن سیرین
محمد بن عبدالباقی بن یوسف الزرقانی
محمد بن عبد اللہ ابوعبداللہ الحاکم
محمد بن عبدالرحمن السخاوی
محمد بن عمر الواقدی
محمد بن عیسی ترمذی ابو عیسی
۸۷ محیصہ
۵ مدین ( قوم)
مدیانی
۴۱ مذحج
۳۶ | مریم بنت عمران
۳۰
مزینہ
۳۲ مسافع بن صفوان
۳۱ | مسروق
۴۲
है
۳۷،۳۴
مسطح بن اثاثہ
مسلم بن حارث
۳۷ مسلم امام مسلم بن حجاج
۴۵۷ صحیح ناصری عیسی بن مریم
۴۴
۸۵۹ | مسیلمہ کذاب
۲۸ مسیو استین برشیمی
۳۶ ۴۳ | مضاض بن عمر و جرہمی
۳۱، ۳۸ | مصعب بن عمیر
۳۱
۲۹۶
۱۸
۱۰۵
۵۳۷
۷۳
۶۹۱
>
۶۸
۶۳۳،۴۸۸
۷۵۶
۶۴۳
۶۳۹
۶۳۹،۶۳۸
۳۵۲،۳۵۰
۳۱
،۲۷۸،۱۱۴،۸۳،۷۴،۲۴
۹۱۷،۸۹۹۰۸۴۰،۶۹۱،۵۰۳،۴۵۴
۹۲۹،۷۵۳،۵۵۵،۱۴۱،۵۲
۹۲۱
،۳۱۰،۲۵۱،۲۵۰،۱۶۵،۱۴۷
۵۶۴،۵۵۵،۵۴۵،۳۲۱
۵۸۵
۴۱۵،۲۰۵،۱۸۹،۱۵۲
۱۰۰ ۹۹ ۹۸
محمد بن عبد الکریم ابوالوليد
محمد بن کعب
محمد بن مسلم بن شہاب زہری
۳۸
۶۸۲
مضر
۳۵ مطعم بن عدی
محمد بن مسلمہ انصاری ۵۴۸،۵۳۴،۵۳۱،۵۳۰، مطلب بن عبد مناف
Page 986
،۷۱۰ ،۷۰۹،۶۸۳۶۸۲،۶۶۳۶۶۱ ، ۶۴۰
۹۱۲،۸۸۰،۸۳۸۰۸۰۹۰۸۰۸
۵۵۰،۱۲۱
میسره
ن.و
نابت بن اسماعیل
نابغہ ذبیانی
نافع مولیٰ ابن عمر
۴۵۷ ،۴۵۲
نائلہ بت
۶۸
نبیه بن الحجاج
۱۵۴
نپولین
نجاشی
۴۹۶
،۳۱۵،۱۸۶،۱۷۴ ۱۷۳،۱۷۲،۱۶۵
۹۲۳٬۹۰۲،۸۹۶،۸۵۱،۳۳۵ تا ۹۲۷
نسائی امام
۴۲
نسربت
۶۸
نسطاس
النظر بن حارث
نضر بن کنانہ
۵۸۱
،۱۸۰،۱۳۱،۱۳۰
۴۲۲،۴۱۶،۴۰۳
۹۵،۹۲
نعمان بن ثابت ابو حنیفہ
۳۲
نعیم
۵۹۵
۶۶۷ تا ۶۶۹
۳۴۴،۱۰
۸۴۳
۷۳
۴۰۳
۶۶۲
۲۱
۴۱۱،۲۴۹
،۱۳۹،۱۱۹،۱۱۸
معاذ بن حارث
معاویہ بن ابوسفیان امیر معاویہ
۷۲۶،۷۱۹،۷۱۸،۵۹۴ ، ۱۴۹ ،۱۴۱
۵۶۹
۵۶۸
۴۹۴
۸۵۱
۴۰۱
۴۰۱،۳۷۱
معاویہ بن مغیرہ
معبد.رئیس خزاعہ
معقل بن بسیار
مغیرہ بن شعبه
مقداد بن اسود ( مقداد بن عمرو )
۰۹۱۰،۸۹۶،۷۴۶ ۹۱۶، ۹۱۷ تا ۹۲۱
۸۵۸۰۸۵۳٬۸۵۲
۴۵۷
۱۶۸
۱۵۴
۹۱۳
۵۸۳
۵۸۴
۶۲
9+1
،۲۲۱،۱۵۰،۱۳۵،۷۴،۵۲
مقداد بن عمرو
مقوقس
مکر زبن حفص
مکحول بن عبد الله
منات بت
منبہ بن الحجاج
منذر بن ساوی
منذر بن عمر و انصاری
منذر بن محمد
منذر ثالث ملک حیره
منصور قلاون
موسیٰ علیہ اسلام
۲۲۲ ۲۲۳، ۲۲۵ تا ۲۲۸، ۲۳۱، ۲۷۹،۲۷۸،۲۵۵، نعیم بن مسعود
۹۱۸،۹۰۱،۸۹۲،۸۳۹ ،۷۷۸ ،۶۶۰۶۷۵،۵۱۸
موسی بن عقبہ
۴۵۷ ،۳۵
نمیلہ بن عبدالله
میور سرولیم سرولیم میور ۸،۴، ۱۱۹،۱۰۹،۷۰،۱۴۰۹، ۱۳۵،
نوح علیہ السلام
،۴۱۵ ،۴۱۴ ،۳۸۰ ،۳۴۴ ،۳۴۳ ، ۲۴۸ ،۲۴۲،۲۰۶،۱۵۴
نوفل بن خویلد
۴۸۶،۴۲۳،۴۲۲، ۵۱۱،۵۰۵، ۶۲۳،۵۲۵ تا ۶۲۷،
نوفل بن عبداللہ
Page 987
۲۲
نوفل بن عبد مناف
نولڈ یکی
نووی امام
نیل
واثلہ بن اسقع
۹۹،۹۷ | ہرقل ۸۹۹۰۸۹۷،۸۷۵،۸۷۴،۱۳۰ تا ۰۹۰۲
۳۴۴
۴۲، ۱۶۹ ہشام بن عمرو
۲۲۱
ہند بنت خدیجہ
۳۵۳ ہند بنت عتبہ زوجہ ابوسفیان
الواقدی محمد بن عمر ۳۶، ۴۰،۳۷، ۳۷۲،۴۳،۴۲،۴۱، ہندز وجہ ابو سفیان
وثیق رومی
وحشی
۵۰۵،۵۰۴،۴۸۱ ، ۶۲۳،۶۲۰،۵۲۱،۵۰۷، ۸۱۷ ہندہ زوجہ ابوسفیان
ود (بت)
ورقہ بن نوفل
۵۵۵،۵۵۴ بنید بن عارض رئیس بنو جذام
۷۹
ہوازن
۶۸ ہود علیہ السلام
۷۰ ھوذه بن علی رئیس یمامہ
۱۹۲
ہمدان
١١٩ | یاسر
۱۲۳، ۱۵۴۷۱۵۳،۱۴۷، یا قوت بن عبدالله الحمودی ابو عبد اللہ
۳۲۱،۳۱۶، ۳۳۸، ۴۱۹ یکی
ولی اللہ شاہ محدث دہلوی
ولید بن عتبہ بن ابوسفیان
ولید بن مغیره
ولید بن ولید
۴۱۹ یحی بن سعید القطان
هی
یحی بن کثیر
یکی بن معین
ہاجرہ علیہا السلام
۷۳ تا ۸۳۷۹ تا ۵۱۴،۸۵
یزدجر و
ہارون
۹۰۱،۲۲۸ ،۲۲۷ ،۲۲۱
ہاشم بن عبد مناف
۹۹ ،۹۸ ،۹۷
یزید بن ثعلبہ ابوعبدالرحمن
یزید بن ربیعہ الاسود
ہالہ ابن خدیجہ
۱۲۲
ہالہ بنت خویلد
ہالہ بنت وہب
۱۹۵
۱۰۳
۴۱۸
یزید بن معاویہ بن ابی سفیان
یزید بن یزید
سیار ( آنحضرت کا خادم)
السعور کا بہن
ہبار بن اسود
۶۸
۹۰۵ تا ۹۱۲۹۱۰
۱۸۸
۱۲۲
۴۲۱
۵۶۳،۵۵۱،۵۴۵
۶۳
۷۶۹
۱۱۷ ،۱۱۰،۱۰۶،۵۱
۵۳،۵۲
۹۲۹
۶۸
۱۵۹
۴۵
۲۲۷،۲۲۱
۲۹
۴۴۶
۴۱ ،۲۵ ،۲۴
۹۱۲
۲۴۹
۹۶
۷۱۸،۷۲۶،۵۹۴
۸۳۷،۵۱۲
۶۹۱
۵۰۳٬۸۱،۸۰
یعقوب علیہ السلام
۱۵۸،۱۴۱،۶۸
ہبل بت
ہذیل
Page 988
۳۰
،۲۲۱،۸۵،۸۴
یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبدالبر.ابو عمرو
۶۳۸ ،۲۲۷
۷۴۲،۲۷۹،۲۰۶،۲۰۵
یوسف بن یعقوب علیہما السلام
یونس بن متی
۲۳
۳۸
۶۸
۶۸
۵۵۴
۲۹
یعقوب بن ابراہیم ابو یوسف
یعوق بت
یغوث بت
یمان
یوسف بن ز کی المزی جمال الدین
Page 989
۸۹۹
،۶۴۸ ،۴۳۰،۴۲۳،۳۶۵،۲۶۸
۹۱۱،۸۹۹ ،۸۹۷
۸۹۹
۹۲۸ ،۹۰۷ ،۹۰۶۹۰۲۸۹۹
۸۵
۲۹۱،۱۷۲،۱۶۵،۵۹،۵۱
۵۸،۴۷
۲۹۲،۱۲۰،۵۹،۵۸،۵۲،۵۱
۸۷۲،۱۶۵
۲۴
مقامات
ایڈیسیا
ایران
ایشیائے کو چک
ایلیا ( بیت المقدس)
ب.،۳۷۳،۳۶۲،۳۶۱،۳۳۳،۳۱۶۰۵۹
،۳۹۲،۳۹۱،۳۹۰،۳۸۸ ،۳۸۶،۳۸۵،۳۸۴
،۴۰۸ ،۴۰۳،۴۰۲،۴۰۱ ،۳۹۸ ،۳۹۷ ،۳۹۳
۴۲۸ ، ۴۲۵ ،۴۲۲،۴۲۱ ،۴۱۶،۴۱۴
۱۷۴
۳۰۰
۹۰۲۹۰۰،۱۱۳
۳۳۷،۸۶،۷۶،۷۴
۴۵۷
۳۷۱،۱۱۱
،۵۴۸،۵۴۷،۵۴۵،۳۹۲،۲۹۱
،۵۶۶،۵۶۲،۵۶۰، ۵۵۶ ، ۵۵۲،۵۴۹
۸۸۵،۵۷۱،۵۷۰،۵۶۹ | بابل
آسٹریلیا
ابوا
ابی سینیاد یکھئے حبشہ
احد
الاحقاف
احمد نگر (ضلع جھنگ)
اریس ( اسم بئر )
اسرائیل
اسکندریہ
افریقہ
افریقہ براعظم
اکسوم (Axsum)
امریکہ (جنوبی)
انگلستان
ایتھوپیا دیکھئے حبشہ
۵۲ بحر احمر
عرض حال بحر ہند
۸۹۵ | بحرین
۲۴۸ بحیرہ احمر
۹۱۷ ،۹۱۶
بدر
۸۷۰،۴۵۷ ،۱۷۲۱۰۱
۹۲۲،۸۹۶،۱۶۵
۱۷۲،۱۶۵
۵۵۲ برک الغماد
۴،۱۹۱ ۴۵ ، ۴۵۶،۴۵۵، | بصره (عراق)
۷۹۰،۵۷۵،۴۵۷ | بصری (شام)
۳۴۴،۱۱۹،۱۰ ، ۴۸۵ | بکه وادی
بواط
Page 990
،۸۶۶،۸۶۵،۸۶۱،۸۵۵،۸۵۳
۸۹۵،۸۷۲،۸۷۰،۸۶۷
190
۵۱
۱۶۴،۵۸
۵۶۹،۵۶۸،۵۶۷
۹۰۷ ،۹۰۶۹۰۲۸۹۹
۴۰۴
و
ง
۶۲۵۳
۳۷۳
۴۷
۵۱،۴۷
،۶۴۷،۵۹۳،۳۰۱ ،۱۹۱،۶۹،۵۲
،۸۱۲،۸۰۷ ،۸۰۶ ،۷۷۱ ،۷۳۸ ،۷۳۴
۹۲۶۹۱۲۸۳۳۸۳۲،۸۳۱
دذرز
۸۰۶،۸۰۴۶۰۸ ،۶۰۷،۵۹
۸۷۱،۸۴۳
۷۵۵،۷۵۴
۲۴۳۲۴۲،۲۰۳
۵۲۴۵۲۳
۹۲۷
۴۸
،۵۸۲،۵۸۱،۵۷۸،۵۷۷
۲۵
بئر معونہ
۵۸۵،۵۸۳،۵۸۲،۲۵۷ تا ۵۹۱،۵۸۸
بیت المقدس ۲۱۳ ۲۱۴، ۲۳۰،۲۲۹،۲۲۴،۲۲۳،۲۱۷،
۳۰۲،۲۳۲،۲۳۱، ۳۷۸ تا ۹۰۲،۸۹۹،۸۴۲،۳۸۰، ۹۲۸ | حراء کوه (جبل)
عرض حال | الحساء
۸۰۶ | حسمی
۵۱
۴۲۴ ،۶۹،۵۲
حضرموت
حمراء الاسد
حمص
حنين
حویلہ
۳۹۷
حیرہ
۵۱
خراء
۳۴۴۹
۷۵۶
۵۲
خلیج عمان
خلیج فارس
۱۹۱
عرض حال
۹۲۷
ج - ج - ح - خ
پاکستان
تبوک
تهامه
جبل الراة
جحفه
جده
جرمنی
جموم
جوف
جونس برگ
۱۰۲،۱۰۱،۵۱، ۱۶۵،۱۴۱تا ۱۶۹
۳۳۵،۳۱۵،۲۸۰،۲۱۰،۱۸۶،۱۷۴،۱۷۲،۱۷۱، دومۃ الجندل
۴۶۴، ۹۲۳٬۹۲۲،۸۹۶،۵۷۹، ۹۲۵ تا ۹۲۷ | ذوالحلیفه
۵۵،۵۲،۵۱،۴۹، ۷۴،۵۹،۵۸، | ذوالقصه
۶۰۷،۵۹۳،۵۲۶،۳۶۴،۲۹۱،۷۹،۷۸، | ذوالمجاز
۶۲۸، ۶۴۷ ،۸۰۶، ۹۲۸،۹۱۴،۸۷۲،۸۱۵ | ذی امر
۲۵۹٬۸۹ | راس کماری (بھارت)
۱۱۱، ۱۹۵ الربع الخالی
۸۴۴،۷۷۰، ۸۵۳٬۸۵۲٬۸۴۸، | رجیع
چنیوٹ
چین
حبشه
حجاز
حجر
حون
حديدة
Page 991
روحاء
روس
روم
روما
رومية
زمزم
سبین
سفوان
سلع ( پہاڑی)
سخ
سیف البحر
شام
۵۸۷،۵۸۶،۵۸۵
۵۶۸ ،۴۰۱
۲۶
صفا
۷۹۴ ،۷۹۳
صنعاء (شام)
۹۰۷ ،۸۷۴،۴۳۰،۴۲۸،۲۴۱،۵۳،۳
ضریہ
،۸۹۹،۸۹۸ ،۸۹۷ ،۸۹۶
طائف
۹۰۵،۹۰۲،۹۰۰ تا ۹۰۷
۹۰۶۹۰۲
۲۲۰،۱۰۹ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۹۵،۸۷ ،۶
سیش
۹۲۷
۳۷۳
۴۸۶
۸۷۳۸۷۲،۳۷۲
،۱۰۴۹۸ ،۸۸،۶۹ ،۵۹،۵۸ ،۵۱ ،۴۷
،۲۵۲،۲۱۰،۲۰۷ ،۱۸۱،۱۷۵،۱۴۱،۱۴۰ ،۱۲۱،۱۱۶،۱۱۳
،۵۲۰،۳۹۵،۳۸۴،۳۶۷ ،۳۰۸،۳۰۷ ،۲۹۱،۲۶۸
،۷۴۱،۷۳۸ ،۶۵۱،۶۰۸ ،۶۰۷ ، ۵۹۳،۵۶۶،۵۲۶
۹۱۸،۹۰۲۹۰۰،۸۹۸ ،۸۷۲،۸۰۶۰۷۶۹ ،۷۵۷
شعب ابی طالب
شعیب بنی ہاشم
شعیبہ ( بدرگاه بحراحمر )
۴۱۵،۲۰۳،۱۹۲،۱۸۹ ،۱۸۷ ،۹۹
۱۰۵
۱۶۶
وے
ง
ص.ض.ط
۱۴۶،۱۴۵،۱۴۱ ،۷۵
۶۵۱،۵۱
۷۴۹
،۱۵۲،۱۱۷ ،۶۹،۶۸ ،۶۰ ، ۴۹ ،۴۸
۲۰۳ تا ۲۴۲،۲۰۹،۲۰۶، ۲۷۸،۲۴۹،۲۴۸،۲۴۴،
۷۴۲،۴۱۵،۳۷۵،۳۷۴،۳۶۵،۳۳۵،۳۲۵،۳۰۸
طرف
عدوا ADOWA
ع غ
عراق
عرب
۵۲۶،۴۲۳،۳۷۵،۱۸۱،۱۳۹،۷۳۴۷
۳ تا ۱۱،۱۰،۵، ۳۹،۳۸،۳۵، ۴۷ تا ۵۳،
۵۷۰۵۵ تا ا۷ ۷۴ ، ۷۷ تا ۸۷،۸۵،۷۹ تا ۹۲،۸۹،
۹۵، ۹۷، ۱۰۱ تا ۱۱۶،۱۰۳ تا ۱۲۳،۱۱۸، ۱۲۹،۱۲۸، ۱۴۸،
،۲۰۵،۲۰۳،۱۸۵،۱۸۱ ، ۱۷۴ ، ۱۷ ۲۰۱۶۶ ۱۶۵،۱۶۲،۱۵۱
۲۳۰،۲۱۰، ۲۴۱، ۲۴۲ تا ۲۴۴، ۲۴۸ ، ۲۶۸،۲۶۰،۲۵۴،
۲۷۸ تا ۲۸۲ ، ۲۹۱ تا ۳۱۵،۳۱۲،۳۱۰،۳۰۳،۲۹۴،
۳۱۸ تا ۳۲۲،۳۲۰، ۳۲۵، ۳۲۸، ۳۳۶،۳۳۴، ۳۳۷تا
۳۵۳،۳۴۴،۳۴۰ تا ۳۵۵، ۳۷۵،۳۷۱،۳۶۵،۳۵۸،
۳۸۳،۳۸۰، ۳۸۹، ۳۹۶، ۴۰۶ تا ۴۰۸ ، ۴۱۷ ، ۴۲۰،
،۴۵۶،۴۵۳،۴۳۱،۴۳۰،۴۲۵،۴۲۴ ، ۴۲۳،۴۲۲
۴۷۶ ، ۴۸۵ تا ۴۸۸، ۴۹۹، ۵۱۱،۵۰۹ ،۵۲۴،۵۲۰،
۵۲۹،۵۲۷ تا ۵۳۲،۵۳۰ تا ۵۶۳،۵۴۵،۵۴۳،۵۳۵،
۵۷۰۰۵۶۶ تا ۷۶ ۵ ۵۸۲۰، ۶۰۷،۵۹۳،۵۸۶،۵۸۵،
،۶۴۷ ،۶۴۶،۶۳۱،۶۲۷ ،۶۱۹ ،۶۱۸ ،۶۱۴،۶۱۳
Page 992
۴۰۱،۳۲۰،۳۰۱،۲۹۶،۲۹۵،۲۹۴
۵۲۶
۸۳۲،۵۱۲
۵۲۳،۵۱۱
ا۷۷، ۹۱۲،۸۰۸
۹۲۱ ،۹۱۱،۸۹۹،۸۹۸ ،۸۹۷
۵۱۲
۴۲۳
۱۴۶،۱۴۵،۱۴۱ ،۷۵
191
۲۰۸،۲۰۳
۲۷
N
۶۹۷،۶۸۶،۶۸۱،۶۷۲،۶۶۹،۶۵۸، ۷۱۲،۶۹۸، قباء
۷۴۷،۷۳۶،۷۲۹، ۷۴۸، ۷۷۹،۷۷۸،۷۵۷، | قرده
۸۳۶،۸۱۶،۸۱۵،۸۰۶،۸۰۳،۷۹۲،۷۸۴،۷۸۱، | قرقره
۸۴۲، ۹۰۵،۹۰۲٬۹۰۰،۸۵۸٬۸۵۱،۸۴۹، ۹۰۷، قرقرۃ الکدر
۹۱۲، ۹۱۸ ، ۹۱۹ ، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۳۰ قری وادی وادی القریٰ
عرفه
۸۹۳
قطنطنیہ
۵۷۶
عرنه
قطن
عریض
عسفان
عشیرہ
۵۴۵،۵۱۳ | الكدر
العميم
۸۶۵،۸۴۳،۷۶۳،۵۷۸ کراع المهیم
۳۷۳ کوفه
کوه صفا
۲۵۰،۲۴۹
۶۰،۵۹، ۲۰۳،۱۱۷،۷۰ ۲۴۲ لا پلاٹا (جنوبی امریکہ )
مجنه
مدائن
مدین
مل بینہ
۶۵۱
۷۳،۵۲،۵۱
،۹۹ ،۹۸،۷۸ ،۶۶،۵۹،۵۳،۵۱ ،۴۹
،۲۴۶،۲۴۵،۲۱۲،۱۷۴ ،۱۴۸ ،۱۴۷ ، ۱۴۱ ، ۱۱۹ ، ۱۱۰ ،۱۰۴
۲۴۸، ۲۴۹ ، ۲۵۰ تا ۲۵۶،۲۵۲، ۲۶۰،۲۵۹،۲۵۷،
،۲۸۰،۲۷۸ ،۲۷۶۰۲۷۰،۲۶۹،۲۶۸،۲۶۳۲۶۰
۳۰۲۲۲۹۱، ۳۰۶ تا ۳۲۴،۳۲۰، ۳۳۶،۳۳۳،۳۲۵،
۳۳۸ تا ۳۴۱ ، ۳۶۴ تا ۳۶۸، ۳۷۲،۳۷۰ تا ۳۷۴،
۳۸۰،۳۷۶ ، ۳۸۴، ۳۸۵ ، ۳۸۷ تا ۳۹۳، ۳۹۵ تا
۳۹۸،۳۹۶ تا ۴۰۴ ۴۱۴۰، ۴۱۶ تا ۴۲۳،۴۲۰،۴۱۸،
۴۲۵ ، ۴۲۷ ، ۴۸۶،۴۳۸، ۵۱۱،۵۰۹،۵۰۷،۵۰۴ تا
۵۱۶۰۵۱۳ تا ۵۱۸ ، ۵۲۰ تا ۵۳۶،۵۳۳،۵۳۲،۵۲۹،
۵۹،۴۸ ، ۴۷
۷۵۷،۷۵۶،۳۷۲
۳۳۷،۳۳۵،۲۶۶،۲۶۵،۲۶۳۰،۱۳۸
۲۷۷ ،۱۳۶،۱۳۴ ۱۳۳ ۱۲۷ ،۱۲۶
۷۵۳
۹۲۸ ،۹۰۲،۹۰۰،۸۹۶،۲۹۳،۲۴۳
۷۹،۷۸
۸۰۷ ،۸۰۶
۷۳
۷۴۱
عقبه
عكاظ
عمان
عص
غار
ثور
غار حراء
غران (وادی)
غمر (چشمه)
غسان
فق کل
۷۴۶،۷۴۵،۳۸۴،۲۸۹ ،۲۸۷
فاران
فارس نیز دیکھئے اسیران
فدک
فلسطین
قادسیه
قادیان
Page 993
۲۸
۶۰۶۰۶۰۳۰۵۹۷۰۵۹۶،۵۹۵تا۶۲۲،۶۱۹،۶۰۹،
۶۲۹،۶۲۸ ، ۶۳۱ تا ۶۴۶۰۶۴۰،۶۳۵ تا ۶۵۱،۶۴۸،
۲۴۱،۲۳۲ ، ۲۴۲ ،۲۴۳، ۲۴۶،۲۴۵ تا ۲۵۲،۲۵۰
۲۵۸ تا ۲۶۳ ۲۶۵ تا ۲۷۰، ۲۷۶،۲۷۵، ۲۷۸ تا ۲۸۱،
۶۶۵،۶۵۹،۶۵۸، ۶۶۷ تا ۶۷۱۰۶۶۹ تا ۶۷۴
۶۸۵،۶۸۳۶۸۲،۶۷۹،۶۷۷ تا ۶۹۰،۶۸۸، مئی
۶۹۵ ، ۷۱۱ تا ۷۱۳، ۷۳۴، ۷۴۰ ، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، | مواب
۷۵۰ ۷۵۲ تا ۷۵۸، ۷۶۲ تا ۷۶۹،۷۶۴ تا ۷۷۱، موریا
۸۰۶ تا ۸۱۵،۸۱۳٬۸۱۲،۸۰۸، ۸۳۱،۸۱۷ تا ۸۳۸ | مهره
۸۵۳،۵۶۳،۵۰۸،۳۸۶
۷۷۵،۲۵۰،۲۴۹ ،۲۴۲،۱۹۰،۱۲۶،۸۲
۲۹۱
۸۲
۵۱
،۵۲۳،۵۱۲،۵۱۱،۲۵۹،۵۸،۵۲،۵۰،۴۸
،۶۴۶،۶۰۷ ،۵۸۶،۵۸۳،۵۸۲،۵۲۶
۸۱۳٬۸۱۲،۷۵۶۰ ۷۴۹ ،۶۸۲،۶۴۷
۹۰۹،۷۳۶،۷۳۴،۶۹ ،۵۱
،۳۷۴،۲۰۹،۲۰۷ ،۲۰۵،۶۸ ،۶۰
۵۰۸،۳۹۵،۳۷۶،۳۷۵
۲۱۰،۲۰۷
۷۴۲۲۰۶،۲۰۵
۲۲۱ ،۱۷۴
۵۹
۴۲۲،۴۱۴۴۰۳
۸۴۴ ،۷۵
۴۰۱
۵۱۳
A
وہی
بجد
نجران
نخله
،۸۶۹٬۸۶۸۰۸۶۵،۸۶۳٬۸۵۳٬۸۴۳٬۸۴۲
۸۷۰ تا ۸۷۷،۸۷۵۰۸۷۳ تا ۸۸۵،۸۸۴،۸۸۲،
۹۲۹ ،۹۲۸ ،۹۲۰ ، ۹۱۹ ،۹۱۴ ،۹۱۲،۸۹۹
۹۲۷
۸۲،۷۵،۷۴
۶۳۰،۶۲۹
۲۲۹،۲۲۳،۲۱۷
مراکش
مروه
مریسیع
مسجد اقصیٰ
مسجد حرام ۹۲، ۹۹، ۲۱۱ ، ۲۲۰،۲۱۷، ۳۷۷، ۸۶۶،۳۷۹
مسقط
مشقر
۵۱
۵۹
،۷۴۶،۸۵،۸۴،۷۶،۷۳،۵۸
۹۲۱ ،۹۱۹ ،۹۱۷ ،۹۱۶۰۹۱۰،۸۹۹ ،۸۹۶،۸۵۲،۷۸۴
تصيين
نینوا
نیل دریا
۵۶۸،۱۰۲،۱۰۱
و با
۷۳،۶۰،۵۹،۴۸ ۷۴ ۷۵ تا ۸۲،۷۸،
ودان
۸۵، ۸۷ تا ۹۵،۹۲، ۱۹۸ تا ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۶،۱۰۳ تا ۱۱۳، وادی بدر
۱۲۰،۱۱۷ تا ۱۲۲، ۱۲۶، ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۴۲،۱۳۷، ۱۴۴، ۱۴۶، وادی تجون (مکه)
۱۵۳،۱۵۲،۱۴۹ ۱۵۷ تا ۱۶۲،۱۵۹، ۱۶۶ تا ۱۷۲۱۶۸، وادی صفراء
۱۸۲،۱۷۹،۱۷۴ تا ۱۸۴، ۱۸۷، ۱۹۲،۱۹۰،۱۸۹، ۱۹۵، | وادی عریض
۲۰۳ تا ۲۰۵، ۲۱۲،۲۰۹ تا ۲۱۴، ۲۱۶ تا ۲۱۸، ۲۲۵، ۲۳۱، وادی فاطمه
معبد
Page 994
۵۱۲
۷۵۱،۷۴۹،۵۲ تا ۹۲۹٬۸۹۶،۷۵۳
،۸۷ ،۶۸،۵۹،۵۸،۵۱،۴۸ ،۳۹
،۷۳۶،۶۵۱،۲۹۳،۲۱۰ ،۱۴۹ ،۱۰۲،۱۰۱ ،۹۸ ،۹۰
۹۱۲۸۹۶ ۹۱۴ تا ۹۱۶، ۹۲۸
،۴۵۹،۴۵۷ ،۲۳۸ ،۲۳۰،۱۳۹
۷۹۰۷۸۵،۷۶۵،۶۱۷ ،۶۱۶
۳۴۰
بیسار
یمامه
۲۹
1772116
،۴۵۷ ،۳۸۴ ،۳۸۰،۲۸۷ ،۱۵۰، ۵۸
۴۶۴، ۴۸۶،۴۸۵ ، ۶۱۷ | یمن
،۱۴۷ ، ۱۱۰ ،۱۰۴ ،۹۹ ،۹۸ ،۶۹،۶۶۰۵۹
وادی القریٰ
ہندوستان
میثرب
۲۱۰،۱۷۴،۱۵۷، ۲۳۱، ۲۴۴ ،۲۴۵، ۶ ۲۴ ، ۲۴۷ تا ۲۵۰
بیرون
میروشلم
۲۵۵،۲۵۴، ۲۵۸ تا ۲۶۱ ۲۶۹،۲۶۶ ، | منبع
۲۹۱،۲۸۰،۲۷۸ تا ۲۹۳ ، ۴۰۷ | یورپ
VVL
۸۹۹ | یونان
۶۹۱
پریکو
Page 995
جنگ سرایا.غزوات
سریہ ابوسلمہ
سر یہ حمزہ بن عبدالمطلب
سریه دومتہ الجندل
سرایا
سرید زید بن حارثہ بطرف بنوسلیم
سریہ زید بن حارثہ بطرف حسمی
سریہ زید بن حارثہ بجانب طرف
سریہ زید بن حارثہ بطرف عیص
سریه زید بن حارثه بطرف قرده
سریه زید بن حارثہ بطرف وادی القریٰ
سریہ سعد بن ابی وقاص
سریہ قرطا
سریہ عبداللہ بن جحش
سریہ عبیدہ بن الحارث
سر یه عمر و بن امیه
سریہ محمد بن مسلمہ
سریه نخله
غزوہ ابواء
۳۷۲ غزوه احد
غزوات
۵۷۵
۸۰۳
۷۵۶ | غزوہ احزاب
۷۶۹
۷۶۸ غزوہ بدر
۷۵۷،۷۵۶ غزوہ بدر الموعد
۵۷۴،۵۷۳،۵۴۳،۳۹۲
۵۷۵،۵۸۷ ،۶۲۶
،۷۴۷ ،۱۱،۶۸۹،۶۸۲،۳۳۳
۸۸۴،۸۸۳٬۸۱۵،۷۴۸
۴۱۷ ،۳۷۳،۳۶۸
۵۹۶،۵۹۴،۳۵۴
،۷۱۲،۷۱۱،۶۸۲۶۷۴
۸۱۷،۸۰۶،۷۴۵
۵۲۷،۵۲۲۵۲۱،۵۱۶،۵۰۷
۵۳۸،۵۲۶ | غزوہ بنو قریظہ
۳۷۳ | غزوہ بنو قینقاع
۷۴۸ غزوہ بنو لحیان
۷۶۲ تا ۷۶۴، ۷۶۸
۳۷۴ غزوہ بنوا بنی مصطلق
۶۴۴۶۱۱
۳۷۱ غزوه بنونضیر
۶۸۷،۵۹۴،۵۹۰،۵۸۷
۸۳۵،۸۳۳ | غزوه بواط
غزوہ بئر معونہ
۳۷۵
۷۵۴
۶۲۶
سریہ وادی نخله
۵۰۸ | غزوہ تبوک
۳۹۵ | غزوه حدیبیه
غزوہ حمراء الاسد
غزوہ حنین
۷۴۷
۴۱۶،۳۳۴
Page 996
۵۹۴،۵۷۸،۵۷۵،۵۷۱،۵۷۰
۸۱۳٬۸۱۲،۶۴۶،۶۳
،۱۹۵،۱۷۴،۱۵۳،۱۲۲،۷۰،۶۳
۳۸۴،۳۷۷ ،۳۷۰ ،۳۱۰،۲۹۴،۲۵۷ ،۲۵۵،۲۱۲
۳۹۳،۳۸۷، ۳۹۵،۳۹۴، ۴۲۰ تا ۴۲۵، ۴۲۹،۴۲۸،
،۵۲۸،۵۲۷ ،۵۲۵ ،۵۲۱،۵۱۸ ،۵۱۷،۵۱۵،۵۱۲،۵۱۱
۸۸۴،۷۵۷ ،۵۹۷،۵۸۹،۵۷۰،۵۴۳
۶۲
۳۱۴۲۹۳،۲۵۵،۲۵۱،۲۴ ۶،۲۴۵
۱۴۰
۶۷۲
۸۰۷ ،۲۱۲،۱۷۴
۱۱۸،۱۱۷
۲۵۶
۵۵۵،۱۴۷ ،۱۴۱
۳۱
غزوہ خندق
،۶۶۶،۶۵۸،۳۳۳۴۹
غزوہ خیبر
۶۷۴، ۸۸۵،۶۹۲۶۷۷ | جنگ احزاب
۹۲۰ | جنگ بدر
غزوہ دومۃ الجندل
۶۰۷
غزوہ ذات الرقاع
غزوہ ذی امر
۵۲۴
۵۲۴،۵۲۳
غزوہ سفوان
۳۷۳
غزوہ سویق
۵۴۳،۵۲۱،۵۱۳،۵۱۲ | جنگ بسوس
غزوہ طائف
۵۵۵ | جنگ بعاث
غزوہ عشیره
۳۷۳ جنگ جمل
غز وہ عکاشہ بن محض
۷۵۳ جنگ خندق
غزوہ قرقرة الكدر
غزوہ مریسیع
۵۲۳٬۵۱۱ | جنگ خیبر
۶۴۳ | جنگ صفین
غزوہ موتہ
۹۲۶،۷۷۱ | جنگ فجار
غزوه ودان
۳۷۱،۳۷۰ | جنگ موتہ
جنگ
جنگ یرموک
جنگ یمامه
جنگ احد
،۲۵۷ ،۲۵۶،۲۰۶،۱۵۳،۶۳
،۵۶۹،۵۵۰،۵۴۳،۴۲۱،۳۸۹،۳۰۸
Page 997
۳۲
کتابیات
BIBLOGRAPHY
۱- قرآن کریم
قرآن کریم اور تفاسیر
-- تفسیر کبیر : محمد بن عمر بن الحسین امام فخر الدین رازی (۵۴۳ ۵ تا ۶۰۶ ھ )
البحر الحيط : الشیخ اشیر الدین ابو حیان بن محمد بن یوسف الاندلسی ( وفات ۷۴۵ھ )
۴- تفسیر ابن کثیر : حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر ابن کثیر الدمشقی ( ۷۰۰ ۵ تا ۷۷۴ھ )
۵- الاتقان فی علوم القرآن : عبدالرحمن بن ابی بکر علامہ جلال الدین السیوطی ( وفات ۹۱۱ھ )
-۶- لباب النزول فی اسباب النزول : عبدالرحمن بن ابی بکر علامہ جلال الدین السیوطی ( وفات ۹۱۱ھ )
۷- ارض القرآن: سید محمد سلیمان ندوی (۱۳۰۲ھ تا ۱۳۷۱ھ )
احادیث و علوم حدیث
- جامع صحیح بخاری: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری (۱۹۴ھ تا ۲۵۶ھ)
-۲- جامع صحیح مسلم : ابوالحسین مسلم بن حجاج بن مسلم نیشا پوری (۲۰۲ ھ تا ۲۶۱ھ)
- جامع صحیح ترمذی: محمد بن عیسی الترندی (۲۰۹ھ تا ۲۷۹ھ)
۴.سنن ابوداؤد : سلیمان بن اشعث السجستانی (۲۰۲ ۵ تا ۲۷۵ھ)
۵- سنن ابن ماجہ: ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه ( وفات ۲۸۳ھ)
سنن نسائی: ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی (۲۱۵ ۵ تا ۲۹۵ھ)
موطا امام مالک: امام مالک بن انس ( ۹۳ ۵ تا ۱۸۹ھ)
-4
-
Page 998
۳۳
-۸- مسند احمد بن حنبل : احمد بن محمد بن حنبل.ابو عبد اللہ (۱۶۴ھ تا ۲۴۱ھ )
۹- کنز العمال ( في سن الاقوال والا فعال): شیخ علاؤالدین المتقی بن حسام الدین ( وفات ۹۷۵ھ)
سنن دار قطنی : ابوالحسن علی بن عمر دار قطنی (۳۰۶ ۵ تا ۳۸۵ھ)
-9
11- سنن بیہقی: احمد بن حسین ابو بکر بیہقی (۳۸۴ ۵ تا ۲۵۶ھ)
۱۲- مشکوۃ المصابیح: شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب التبریزی (وفات ۵۷۴۳)
تلخيص الصحاح ( المختصر للصحاح الستة ): ابن قیم الجوزی عبد الرحمن بن علی بن محمد ( ۵۱۰ ۵ تا ۵۹۷ھ )
۱۴- جامع الصغير : علامہ جلال الدین السیوطی ( وفات ۹۱۱ھ )
۱۵- مقدمہ ابن صلاح تقی الدین ابو عمر عثمان الشهر زوری المعروف بابن صلاح اصابہ فی معرفۃ الصحابہ ابن حجر عسقلانی
(۱۱۸ھ تا ۱۲۴۳ھ)
۱۶- تہذیب التہذیب: ابن حجر عسقلانی حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر ( وفات ۸۵۲ھ)
۱۷- میزان الاعتدال: شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد الذہبی ( وفات ۷۴۸ ھ )
۱۸- تاریخ كبير في الاحاديث والرواة: امام بخاری محمد بن اسماعیل (۱۹۴ھ تا ۵۲۵۲ )
19 احجم الكبير الملطبرانی: ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبرانی (۲۶۰ ۵ تا ۳۶۹ھ)
۲۰ موضوعات کبیر : ملاعلی بن سلطان محمد القاری (وفات ۱۰۸۵ھ )
فتح الباری فی شرح صحیح بخاری: ابن حجر عسقلانی شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی ( وفات ۸۵۲ھ )
فتح المغیث فی شرح حدیث : زین الدین عبدالرحیم بن الحسین ( وفات ۸۰۵ھ)
-۲۱
-۲۲
-۲۳ - اکمال شرح صحیح مسلم: ابوعبدالله حمد بن خلفه الوشتاتی ( وفات ۵۸۲۸)
۲۴ - سبل السلام شرح بلوغ المرام : محمد بن اسماعیل ایمنی (وفات ۵۵۶۲)
تاریخ سیرت
1- سيرة ابن اسحاق : محمد بن اسحاق (وفات ۱۵۱ھ )
۲- سیرۃ ابن ہشام : ابومحمد عبد الملک بن ہشام ( وفات ۲۱۳ ھ )
۳- طبقات ابن سعد
۴- سیرت حلبیہ
المواہب اللدنیہ: شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد القسطلانی ( وفات ۹۲۳)
۶ - شرح المواہب اللہ نبیہ: محمد بن عبد الباقی الزرقانی (۱۰۲۵ھ - ۱۰۹۰ھ)
ے.نور العمر اس فی شرح عیون الاثر : برہان الدین ابراہیم بن محمد اعلمی ( وفات ۱۴۸ھ)
Page 999
۳۴
- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: قاضی عیاض المغربی (۴۶۳ ھ -۵۲۹ھ )
- الروض الانف شرح سیرت ابن ہشام: ابوالقاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهیلی (وفات ۵۸۱ھ)
۱۰- طحاوی: احمد طحاوی (۲۳۳ھ - ۳۱۳ھ)
۱- تاریخ طبری: ابو جعفر محمد بن جریر الطبری (۵۲۲۴ - ۳۱۰ھ)
۱۲ کتاب المغازی: محمد بن مسلم بن شہاب الزھری ( وفات ۱۲۴ھ )
-۱ المغازی موسی بن عقبہ ( وفات ۱۴۱ھ)
۱۴ مغازی الرسول : ابو عبد الله محمد بن عمر الواقدی (۱۳۰ھ - ۲۰۷ھ)
۱۵ کتاب المعارف: عبدالله بن مسلم بن قتیبہ ( وفات ۲۷۶ھ)
۱۶ - زاد المعاد: ابن قیم الجوزی عبد الرحمن بن علی بن محمد (۵۱۰ھ -۵۹۷ھ )
۱۷- وفیات الاعیان: ابن خلکان قاضی شمس الدین احمد بن محمد ( وفات ۶۸۱ ھ )
۱۸ - المزهر: جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی ( وفات ۹۱۱ھ)
19 تاریخ الکامل ابن اثیر عزالدین ابو حسن علی (۱۱۶۰ھ - ۱۲۳۴ھ )
-۲۰- وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى: نورالدین السمہودی (وفات ۵۸۸۶)
۲۱- تاریخ مکه از رقی ابوالولید محمد بن عبد الکریم (وفات ۲۲۳ھ)
۲۲ فتوح البلدان البلاذری: ابو جعفر احمد بن سکی (۲۷۲ھ)
۲۳- معجم البلدان یاقوت حموی: شہاب الدین ابو عبد اللہ یا قوت بن عبد اللہ (وفات ۶۲۶ ھ )
۲۴ - صفة جزيرة العرب : ابن حائک ابو محمد حسن بن احمد الہمدانی (وفات ۳۳۴ھ)
۲۵- تاریخ الا اسلام السیاسی : ڈاکٹر حسن بن ابراہیم مصر (۱۸۳۱ء ۱۹۱۱ء)
۲۶ - التوفيقات الالہامیہ (ہجری.عیسوی کیلنڈر): محمد مختار باشا مصری (۱۲۱۵ھ - ۱۲۷۸ھ )
-1
-٣
اسلامیات
مجمع البحار: شیخ محمد طاہر گجراتی (۹۱۰-۹۸۶ھ)
- عوارف المعارف: شیخ شہاب الدین عمر بن عبداللہ السہر وردی ( وفات ۶۳۲ ھ )
- تعطیر الانام (تعبیر الرؤيا): عبدالغنی بن اسماعیل النابلسی (۱۰۵۰ھ -۱۱۲۳ھ )
- ازالۃ الخفاء عن خلافة الخلفاء : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ( وفات ۶ ۷ ااھ )
۵- کشف الغمہ عن جميع الامة : محمد بن عبد الوہاب بن احمد الشعرانی ( وفات ۳۵۳ھ )
کتاب الخراج : امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم ( وفات ۱۸۲ ھ )
-Y
Page 1000
۳۵
۷- بداية المجهد : ابن رشد قرطبی ابو ولید محمد بن احمد بن رشد (۵۵۲۰-۵۹۵ھ )
کشف الظنون: مصطفییٰ بن عبد اللہ حاجی خلیفہ کا تب چلیپسی
-1
کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام وخلفاء سلسلہ
براہین احمدیہ چہار حصص: ۱۸۸۰ء ۱۸۸۴ء
-۲- سرمه چشم آرید: ۱۸۸۶ء
- ازالہ اوہام :
-۴
۱۸۹۱ء
کشتی نوح: ۱۹۰۲ء
۵- براہین احمدیہ حصہ پنجم : ۱۹۰۸ء
۶- چشمه معرفت: ۱۹۰۸ء
ے.منن الرحمن : ۱۹۱۵ء
-^
-9
فصل الخطاب: حضرت الحاج حکیم نورالدین خلیة امس الاول ( طبع اول ۱۳۹۵ )
- تقدیر الہی تقریر حضرت اصلح الموعود مرزا بشیر الدین محمود احمد جلسه سالانه قایان (۱۹۱۶ء)
عربی ادب ولغات
ا تاج العروس: امام محب الدین المرتضی ( وفات ۱۸۹ه )
-1
۲- اقرب الموارد: سعید الخورى الشر تونى اللبنانی
- دیوان الحماسة : ابو تمام حبیب بن اوس الطائی (۱۸۸ھ تا ۲۲۲ھ )
م کتاب الشعر والشعراء: ابن قتیبہ محمد عبد اللہ بن مسلم (۲۱۲ ۵ تا ۲۷۶ھ)
-
۵ عربی ادب کی تاریخ: پروفیسر نکلسن (۵۱۸۶۸ تا ۱۹۴۵ھ)
بائیل ( عہد نامہ قدیم و جدید)
عیسائیت
ٹیکسٹ اینڈ کینین آف نیوٹسٹامنٹ مصنفہ سر ہنری سوٹر ایم اے
(TEXT AND CANON NEW TESTAMENT BY SIR HENERY SOVTTAR M.A.)
کتب ہندو مذہب
ا پنتھ پرکاش گیانی گیان سنگھ (۱۸۴۵ء تا ۱۹۲۲ء)
-1
- سری کرشن جی لالہ لاجپت رائے (۱۸۳۲ء تا ۱۸۹۸ء)
Page 1001
۳۶
- منوسمرتی اردو: ( ترجمه منو شاستر سنسکرت ہندو دھرم ) ماسٹر آ تمارام جی (وفات ۱۹۱۳ء)
-۴ منو شاستر سنسکرت: از فرمودات منومها راج رشی
- یوگورکرشن پنڈت جمویتی (وفات ۱۸۴۸ء)
انسائیکلو پیڈیاز
ا انسائیکلو پیڈیا آف اسلام
۲.انسائیکلو پیڈیا بلیکا
۳.انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا
-۴- جیوش انسائیکلو پیڈیا
-۵- چیمبرز انسائیکلوپیڈیا
مستشرقین اور مغربی مصنفین کی کتب
1- CALAPHATE BY SIR WILLIAM MUIR (1883)
2- LIFE OF MOHAMMAD BY SIR WILLIAM MUIR (1861)
3- MOHAMMAD BY MARGOLIUS SIDNY (1894)
4- MOHAMMAD AND THE RISE OF ISLAM BY MORGOLIOUTH D.S.(1914)
5- THE HISTORY OF THE NATIONS BY HUTCHINSON (LONDON 1886)
6- HISTORIAN'S HISTORY OF THE WORLD BY HENRY W.SMITH
(LONDON 1884)
7- THE FALL OF THE ROMAN EMPIRE BY EDWARD GIBBIN (LONDON)
ا الهلال مصر: نومبر ۱۹۰۴ء
اخبارات ورسائل
- ریویو آف ریلیجنز اردو قادیان
ا - ریویو آف ریلیجنز اردو اگست ۱۹۰۶ء
ii - ریویو آف ریلیجنز اردواگست ۱۹۱۰ء
iii - ریویو آف ریلیجنز اردو جنوری ۱۹۳۴ء
۳.ہندوستان ٹائمنر دہلی: مورخه ۲۹ را پریل ۱۹۲۸ء