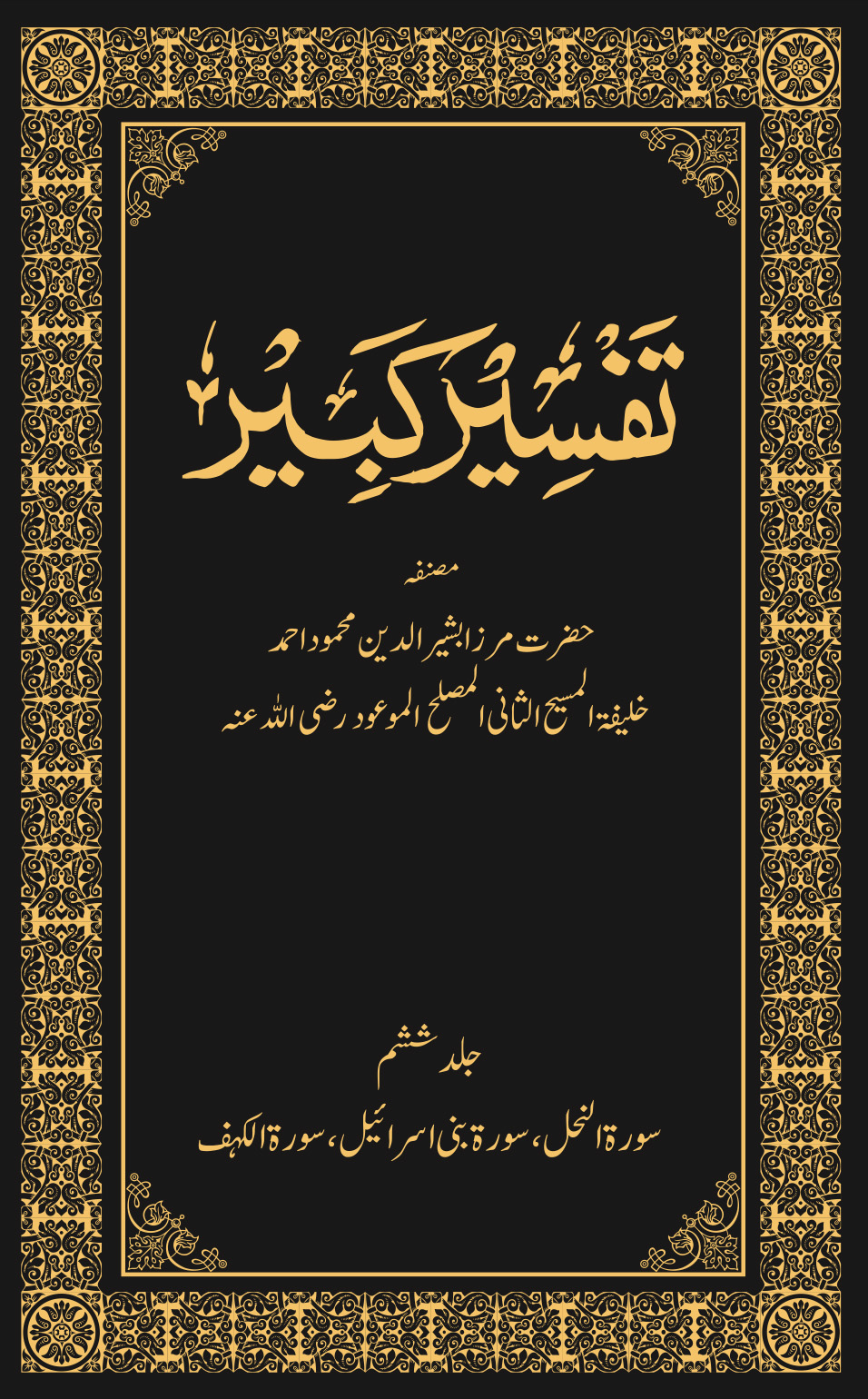Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 6
Content sourced fromAlislam.org
Page 4
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَـحْمَدُہٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ پیش لفظ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے مامور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عظیم الشان رحمت کے نشان کے طور پر پسر موعود کی بشارت عطا فرمائی جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعودؓ کے وجود میں پوری ہوئی.اور کلمات الہامیہ آپ کے وجود مسعود میں جلوہ گر ہوئے.ان میں سے ایک یہ ہے کہ ’’اسے علوم ظاہری و باطنی سے پُر کیا جائے گا.‘‘ قرآن مجید فرقان حمید کےوہ علوم و معارف بھی آپ کو سکھائے گئے جو اس سے پہلے منکشف نہ تھے.چنانچہ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ’’اس تفسیر کا بہت سا مضمون غور کانتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کاعطیہ ہے.‘‘ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر تحریر فرمائی اور اس کے مطالب و معانی اور نکات عجیبہ کو ظاہر و باطن میں پھر زندہ فرما دیا.یہ تصنیف لطیف موسوم بہ تفسیر کبیر اس مذکورہ بالا بشارت کی صداقت کاایک زندہ ثبوت اورشاہد ناطق ہے اور لاریب قرآنی علوم و معارف کا ایک بیش بہا خزانہ ہے جو خدا تعالیٰ نے موجودہ زمانہ کی ضرورتوں کے موافق ظاہر فرمایا ہے.تفسیر کبیر کی پہلی جلد ۱۹۴۰ء میں اشاعت پذیر ہوئی بعدہٗ مختلف وقتوں میں اس کی کل ۱۱ جلدیں شائع ہوئی تھیں.حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اوائل خلافت میں ہی ارشاد فرمایا کہ تفسیر کبیر کی صد سالہ جوبلی کے تحت دوبارہ اشاعت کی جائے.چنانچہ اس کے پازیٹو بنوا کر گیارہ کی بجائے دس جلدوں میں شائع کیا گیا.حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اس علمی خزینہ کی اشاعت کا تازہ ایڈیشن طبع کروانے کی ہدایت فرمائی ہے.پہلی طباعت کتابت ہوکرشائع ہوئی تھی اور باریک قلم سے
Page 5
سُوْرَۃُ النَّحْلِ مَکِّـیَّۃٌ سورۃ نحل.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ مِائَۃٌ وَّ تِسْعٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰیَۃً وَسِۃَّ عَشَرَ رَکُوْعًا اوربسم اللہ سمیت اس کی ایک سو انتیس آیتیں ہیں اورسولہ رکوع ہیں.یہ سورۃ مکی ہے اس سورۃ کے متعلق مفسرین کاقو ل ہے ھٰذِہِ السُّورَۃُ مَکِّیَّہٌ کُلُّھَاقَالَہُ الْحَسَنُ وَالْعَطَاءُ وَعِکْرَمَۃُ وَجَابِرٌ یعنی یہ سورۃ سب کی سب مکی ہے.حسن عطا ءاورعکرمہ اورجابر نے اسی خیال کا اظہار کیا ہے.قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِلَّا ثَلَاثَ اٰیَاتٍ مِنْھَا وَھِیَ مِنْ قَوْلِہ تَعَالٰی.وَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِلٰی قَوْلِہِ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (النحل :۹۶ تا ۹۸).حضرت ابن عباس ؓ کاقول ہےکہ یہ سورۃ سب مکی ہے سوائے تین آیتوں کے.جو وَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ سے شروع ہوکرلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَپر ختم ہوتی ہیں بعض دوسرے کہتے ہیںکہ بیشک تین آیتیں غیر مکی ہیں.مگر وہ اس سورۃ کے آخر میں وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ سے لے کر وَ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ تک ہیں.بعض کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل تین آیات مدنی ہیں (۱)وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ والی آیت نَزَلَتْ فِی الْمَدِیْنَۃِ فِیْ شَأْنِ التَّمْثِیْلِ بِحَمْزَۃَ وَقَتْلٰی اُحُدٍ.یعنی یہ آیت حضرت حمزہؓ اوردیگر شہیدانِ اُحد کے مُثلہ کرنے کے واقعہ کے متعلق نازل ہوئی تھی.(۲)وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ والی آیت(۳)ثُمَّ اِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِیْنَ ھَاجَرُوْا والی آیت.بعض کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے ابتداء سے پہلی تین آیات تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ تک مدنی ہیں.اورباقی تمام سورۃ مکی ہے.قتادہ نے اس کے بالکل برعکس کہا ہے.وہ کہتے ہیں پہلی تین آیتیں مکی ہیں.اورباقی سورۃ مدنی ہے.(البحر المحیط زیر آیت اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ۠...) یورپین مصنفین میں سے ویری ؔ نے ساری سورۃ کو آخری زمانہ کی مکی سورتوں میں سے قرار دیا ہے.نولڈک نے سوائے آیات ۴۴،۱۱۲، ۱۲۰، ۱۲۱،۱۲۶کے باقی سب سورۃ کو مکی قرار دیا ہے.(چونکہ اس نسخہ قرآن کریم میں بسم اللہ کو آیت شمار کیاگیا ہے اس لئے ایک ایک عدد بڑھادیاگیاہے.نولڈک نے ۴۳،۱۱۱،۱۱۹،۱۲۰،۱۲۵ لکھا ہے )سیلؔ نے آخری تین آیات کو مدنی قرار دیا ہے اورباقی تمام سورۃ کو مکی.وائل( WEIL )نے بڑے زور سے سیل کی بات کو رد کیاہے اورکہتا ہے کہ یہ بھی مکی ہی ہیں(وہیریز کمنٹری آن قرآ ن جلد ۳) وجہ تسمیہ اس سورۃ کانام نحل رکھا گیاہے.کیونکہ اس میں نحل کی وحی کا ذکرکے بتایاگیاہے کہ تمام کارخانہء عالم وحی
Page 6
پر چل رہاہے.اوریہی مضمون اس سورۃ کا محوری نقطہ ہے.دوسرے اس میں جہا د کاپہلی دفعہ ذکر ہے.چونکہ اس پر اعتراض ہوناتھا.نحل کی مثال سے اشار ہ کیا کہ اس میں شہد بھی ہے اورڈنک بھی.مگر ڈنک کم اورشہد زیادہ.اسی اصول پر جہاد کاقیام ہے.جس کی غرض صرف روحانی شہد کی حفاظت ہے.سورۃ کے مضامین میرے بتائے ہوئے قاعدہ کے مطابق کہ سورتوں کے مضامین حروف مقطّعات کے تابع ہوتے ہیں.اورجن سورتوں کے شروع میں مقطعات نہیںہوتے.وہ اپنے سے پہلی سورۃ کے جس کے پہلے مقطعات ہو ں.مضمون کے لحاظ سے تابع ہوتی ہیںاوراس میں اُسی سورۃ کے مضامین کا تسلسل ہوتاہے یہ سورۃ سورئہ حجر کے مضمون کے تسلسل میں ہے.اوراسی کے مضمون کو نئے پیرایہ میں جاری رکھا گیا ہے.یہ سورۃ سورۃ حجر کے مقطعات کے ماتحت ہے سورۃ حجر کے شروع میں الٓرٰ کے حروف ہیں جس کا مفہوم اَنَااللّٰہُ اَرٰی ہے یعنی میں اللہ دیکھ رہاہوں.اس سورۃ میں انہی صفت کے مضمون کو نئے پیرایہ میں اورنئے اسلوب سے بیان کیاگیا ہے.اس میں بتایاگیاہے کہ کلام الٰہی کیاشان رکھتا ہے اوراس کی کیاضرورت ہے.اوراس کے اندر کیا قوتِ جاذبہ ہوتی ہے.اورثابت کیا ہے کہ قرآن کریم جو تمام کتب سے کامل کتاب ہے.اس کی قوت جذب اورقوت قدسی کی توحد ہی نہیں.پھر مسلمانوں کی کامیابی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے.پچھلی سورۃ کے ساتھ اس کامزید جوڑ یہ بھی ہےکہ پہلی سورۃ کے آخر میں’’ اِنَّ السَّاعَۃَ لَاٰتِیَۃٌ ‘‘اور’’ فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ‘‘کہہ کر کفار سے عذاب کاوعدہ کیاتھا.اب اس سورۃ میں اَتٰی اَمْرُاللّٰہِ کہہ کر یہ بتایاہے کہ وہ موعود وقت اب آہی گیا ہے.پہلی سورۃ کے آخر میں تواٰتِیَۃٌ فرمایاتھاکہ عذاب کو آیا ہی سمجھو اوراس سورۃ کواَتٰی سے شروع کیاہے کہ وہ آہی گیاہے.یہ قرآن کریم کامحاورہ ہے کہ وہ کسی امر کے قطعی ہونے پر ماضی کے صیغہ سے دلالت کرتاہے.اسی طرح جلد ظاہر ہونے والے امور کوبھی ماضی کے صیغہ سے ظاہر کرتا ہے.کیونکہ جو بات ہوچکی ہو.اس کے متعلق کو ئی شک باقی نہیں رہتا.اسی طرح ماضی کے لفظ سے اس امر پر بھی زو ردیاجاتاہے کہ وہ اس قدر قریب ہے کہ اُسے ہو چکا ہواہی جانو.اردومیں بھی کہتے ہیں کہ بس اُسے آیاہواہی سمجھو.یعنی اس کی آمد نہایت قریب ہے ان الفاظ سے بھی معلوم ہوتاہے کہ یہ سورۃ بالکل ہجرت کے قریب نازل ہوئی ہے.خلاصہ مضمون اس سورۃ کاخلاصہ مضمون یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں بتایاجاچکاہے.اس کی سچائی کے ظاہر ہونے کا وقت بالکل قریب آگیا ہے.یہ سوال کہ یہ کلام کس پر نازل ہواہے.بالکل بے حقیقت ہے.معترض اتنا تودیکھے
Page 7
کہ انسان کی جسمانی پیدائش کیسی حقیر ہے.پھراُسے ترقی دے کر اللہ تعالیٰ نے کس قدرانعامات کا وارث کردیاہے.اسی طرح اگر خدا تعالیٰ روحانی عالم میں کسی آدمی کو جوبظاہربے حقیقت نظرآتاہوبڑھادے اورترقی دےدے.تویہ کیوں خیال نہیں کرتے کہ اس کے اندر بھی کوئی مخفی قابلیتیں ہوں گی.جس خدا نے دنیا کے عارضی سفروں کی ضروریات بہم پہنچائی ہیں.وہ دائمی سفر کی ضروریات کو کیونکر نظر انداز کردے گا.اللہ کے سوااس ضرورت کو نہ لوگ خود پوراکرسکتے ہیں اورنہ اُن کے معبود.پس خدا تعالیٰ کوپانے کا صحیح اورقریب ترراستہ اور اس راستہ پرچلنے کو سہل کردینے والے اسباب خدا تعالیٰ ہی بتاسکتاہے.اور وہی بتاتا ہے.آگے انسان اس میں دخل دے کر اگراپنے لئے مشکلات پیداکرلے.تواس کی ذمہ داری اس پر ہے.پھر بتایاہے کہ جو اس راستہ پر چلتے ہیں.ان سے کیاسلوک ہوتاہے.اورجو اس پر نہیں چلتے.ان کاکیاانجام ہوتاہے.اوراس سوال پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ انسان کی جزاء اس کے انجام پر مترتب ہوتی ہے.اس لئے یہ کہنا کہ نبی کی بات کو سب لوگ فوراً نہیں مان لیتے.پھر جو پہلے انکار کرکے بعد میں ایمان لائے ہیں.ان کاکیا حال ہوگا.معقول اعتراض نہیں.ماننے والے اورنہ ماننے والے اپنے انجام کے مطابق پوچھے جائیں گے کیونکہ اگلے جہان کاراستہ وہاں سے شروع ہوتاہے جہا ں وہ موت کے وقت ختم ہوتاہے.پھر اس سوال کا جواب دیاکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے ہیں تواس کے پیغامبر کی بات کو کوئی ردّ کس طرح کرسکتاہے.خدا تعالیٰ توقادر ہے.پس جسے اللہ تعالیٰ بھیجے گا اس کی بات سب سے منوالے گااورعقلی جواب کے علاوہ نقلی جواب بھی دیا کہ بعض نبیوں کو تم بھی مانتے ہو.کیا ان کی باتوں کوسب نے مان لیا تھا.یاپہلے دن سے مان لیاتھا.پھر مومنوں کو توجہ دلائی کہ اگر تم خواہش رکھتے ہوکہ تمہارے عزیز اس کلام کو مان لیں تواس کاعلاج یہی ہے کہ اُن کے دلوں کو صاف کرو.اللہ تعالیٰ جبر سے انہیں ہدایت نہ دےگا.کیونکہ جس کے دل میں گمراہی ہو اسے ہدایت دینا مومنوں پر ظلم ہے.کیونکہ بعث بعد الموت کی حکمت باطل ہوجاتی ہے.اس پر کفار کاانکار دہرایاکہ بعث بعد الموت کیا ہے.اس کی کوئی حقیقت نہیں.اوراس کی دلیل یہ دی کہ وہ ایک ضروری شے ہے اورجس امر کی ضرورت ظاہر ہو.الٰہی قاعدہ کے مطابق ا س کاوجود ضروری ہے.پھر بعث بعد الموت کااس دنیامیں ہونے والے بعض امور سے ثبوت دیا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قوموں کابعث کرتاہے.اورہجرت سے اس بعث کا آغاز ہوتاہے.جیساکہ اس نبی کی جماعت سے ہوگا.مومنوں اورکافروں کو جداکرناکامل ترقی کے لئے ضروری ہوتا ہے.پھرجو سب سے اعلیٰ کمال ہے اس کے لئے کیوں اللہ تعالیٰ
Page 8
مومن اورکافرکو الگ نہ کرے گا کہ ہرایک اپنے راستہ پر بلاروک ٹوک چل سکے.اس ضرورت کے پوراکرنے کے لئے روحانی ہجرت کی ضرورت ہے جوموت کے ذریعہ سے ہوتی ہے.اس ہجرت کے بعد مومن اورکافر الگ الگ راستہ پر چل پڑتے ہیں.اورمومن بلاروک ٹوک اپنے خالص انتظام کے ماتحت جنت میں روحانی ترقیات کو حاصل کرنا شروع کردیتے ہیں.مسلمانوں کودنیوی ہجرت کے بعد جو ترقی ہوگی.اُسے کفار دیکھ ہی لیں گے.وہ اسی سے قیاس کرسکتے ہیں کہ مومن روحوں کاکافروں سے الگ کرکے رکھنا ان کی پیدائش کی غرض کے پوراکرنے کے لئے کیساضروری ہے.پھر ہجرت دنیوی کے نتائج کی طرف اشارہ کیاکہ کس کس طرح اس سے کفارپر عذاب آئیں گے اورکس طرح مومنوں کو ترقی حاصل ہوگی.اوراس کی وجہ کوئی دنیو ی ذرائع نہیں ہوں گے.بلکہ محض توحید پرقیام اس کاباعث ہوگا.پھر بتایاکہ آخر ت پر ایمان نہ لانے سے انسانی اعمال میں نقص آجاتاہے.یہ بھی یوم البعث کی ضرورت کاثبوت ہے.پھر بتایا کہ ڈھیل کاملنا اس امر کی علامت نہیں کہ خدا تعالیٰ دین کو قائم نہیں کرناچاہتا.بلکہ انسانی نجات کی اہمیت کو ثابت کرتاہے.دنیا میں ڈھیل کاقانون طبعی عالم میں بھی پایا جاتا ہے.پھر کیوں دین کے بارہ میں نہ ہو.خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نجات دینے کی غرض سے ڈھیل دے کر انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں نجات دیناچاہتاہے.پھر جبر کارد اس طرح کیا کہ بدی کوخوبصورت کرکے دکھاناشیطان کاکام ہے.اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہوسکتا.خدا تعالیٰ کاکام توصرف ہدایت کو بیان کرنا ہے.ہاں وہ اپنے عظیم الشان رحم سے ہدایت کے مزید سامان اس طرح پیداکردیتا ہے کہ کلام الٰہی ہمیشہ مومنوں کے لئے رحمت ثابت ہوتاہے اوراس طرح عقلمندوں پر ظاہر ہو جاتا ہےکہ اللہ تعالیٰ اس راہ کو پسند کرتاہے.پھر بتایا کہ ان کایہ اعتراض ہے کہ اگر یہ سچا ہے توپہلی تعلیموں کی مخالفت کیوں کرتاہے.اوربتایا کہ پہلے نبیوں کو کافر قرار دینا اوربات ہے اوررائج الوقت باتیں جو ان کی طرف منسوب ہیں ان کوماننااوربات ہے.نبی توآتاہی تب ہے جب لوگ پہلی تعلیموںکو جو سچی تھیں مسخ کردیتے ہیں اورجب وہ الٰہی حفاظت سے باہر ہوجاتی ہیں.پھر ایک لطیف مثال دی کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ ہی کے شایان شان ہے.جانورکو دیکھو گھاس کھاتاہے
Page 9
اوردودھ دیتا ہے اوریہ خدا تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی مشین کاکام ہے.اسی طرح انسانی اخلاق جوبہیمیت کے تابع ہوتے ہیں گھاس کی طرح ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہی بہیمی اخلاق کو اپنے الٰہی قانون کے ماتحت لا کراعلیٰ اخلاق بنادیتاہے.پھر نحل کی مثا ل دی کہ اس کے کاموں کو دیکھو کہ وہ بھی تو ایک وحی کے ماتحت عمل کرتی ہے اورمعمولی نباتی اجزاء سے شہد تیار کرتی ہے.اس سے سمجھ لو کہ دنیا کے سب کام ایک وحی خفی کے ماتحت چل رہے ہیں.پھر کیوں نہ انسان کے اخلاق کو اعلیٰ بنانے کے لئے کسی وحی کانزول ہو اورکیوں نہ اس وحی کے نتائج اسی طرح شفاکی صورت میں پیداہوں.جس طرح شہد کی مکھی کے عمل کانتیجہ شفاہوتی ہے ہاں جس طرح شہد کی مکھیوں کی اقسام ہیں اورشہد کے مدارج ہیں اسی طرح انسانوں کے مدارج ہیں.اورگوسب مومن وحی کے تابع ہیں مگرہرایک اپنے ظرف کے مطابق روحانی شہد تیار کرتاہے.پھر ایک اور طرح وحی الٰہی کی ضرورت بتائی اورفرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ترقی دیتا ہے کچھ عرصہ کے بعد اس کی حاصل کردہ ترقیاں ایک خاص گروہ کے قبضہ میں آجاتی ہیں.اور دوسرے لوگوں کے لئے ترقی کاراستہ مسدود ہو جاتا ہے.کیونکہ قوم پر قابض لوگ انہیں باوجود قابلیت کے آگے نہیں آنے دیتے.حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے فضل کاوارث بنایاہے.ان حالات کو سوائے وحی کے کس طرح بدلاجاسکتاہے.یقیناً اس زمانہ کے بڑے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قابل ہیں اس لئے قوم کی باگ پر قابض ہیں.اوران کے دعویٰ کے رد کرنے کاکوئی ذریعہ نہیں ہوتا.سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نئے امتحان کاانتظام کیا جائے.پس اس غرض کوپوراکرنے کے لئے نبی کاآناضروری ہوتاہے جب وہ آتا ہے توظاہرہو جاتا ہے کہ جو لو گ قوم پر حکومت کررہے تھے وہ قابل نہ تھے کیونکہ وہ الٰہی کلام کو ماننے سے محروم ر ہ جاتے ہیں.اورجولوگ ادنیٰ سمجھے جاتے تھے وہ مان جاتے ہیں.اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قابلیت والے اور لوگ تھے.اس طرح اللہ تعالیٰ انسانی حقوق کی پھر سے حفاظت کردیتاہے.اورپھر سے ہرانسان اپنی قابلیت کے مطابق ترقی کرنے لگ جاتا ہے.اورنسلی امتیاز کے نظام کو توڑ دیاجاتاہے.اس امر کی تائید میں ایک اوردلیل دی اورفرمایا کہ جب قومیں اللہ تعالیٰ سے دور ہوجاتی ہیں.توشرک کرنے لگتی ہیں.اوراس طرح ایسے وجودوں سے متعلق ہوجاتی ہیں.جو خیر وشر کے مالک نہیں.اوراس طرح ترقی کے حقیقی سامانوں سے محروم ہوجاتی ہیں.اگرا س حالت کو نہ بدلاجائے.توسب دنیا ترقی سے محروم ہوجائے.پھر فرمایاکہ ایک نقص تووحی سے بُعد کایہ ہوتاہے کہ بعض لوگ جبراً قوم کی با گ لے لیتے ہیں اورلوگوںکو
Page 10
قابلیت کے اظہار کاموقعہ ہی نہیں دیتے.ایک اورنقص بھی پیداہو جاتا ہے اوروہ یہ کہ شرک کی و جہ سے اکثروں کی قابلیتیں مر ہی جاتی ہیں.پھرخدائے رحیم اس حالت کو کس طرح برداشت کرے اس طرح تو وہ اپنے عمل کو خود باطل کرے گایہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پہلے قابلیت دے پھر ا س قابلیت کو مرنے دے یاظالموںکو موقعہ دے کہ اس قابلیت کو ظاہرہونے سے روک دیں.غرض کفار کے دعاوی باطل ہیں اورخدا تعالیٰ کی حکمت چاہتی ہے کہ جو ان ظلموں کے بانی ہیں ان کو تباہ کردے.پس جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ظاہری حفاظت کے سامانوں سے سبق حاصل نہیں کیا انہیں ظاہری حفاظت سے بھی محروم کردیاجائے گا.ا وراس دنیامیں بھی اوراگلے جہان میں بھی وہ جھوٹی حفاظت جوشرک کے رنگ میں انہوں نے اپنے لئے تجویز کی تھی ان کی ذلت کاموجب ہوگی.لیکن بتایا کہ ظالمو ں میں بھی ہم فرق کریں گے.جو گمراہ کرنے والے ہیں زیادہ سزاپائیں گے اورجوجہالت سے ان کے تابع ہوئے کم سزاپائیں گے.پھر فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں کہ جن تغیر ات کا ہم نے ذکر کیا ہے اس کے سامان کیسے واضح ہیں اول قرآن کریم میں اندرونی شہاد ت موجود ہے کہ وہ ایک مکمل تعلیم پرمشتمل ہے پھر اس کی تعلیم ترقی کی طرف لے جانے والی ہے.پھرعملاً اس پر چلنے والے برکتیں پاتے ہیں.اس کے بعد کامل تعلیم کی بعض مثالیں بیان کیں.اس پرکفار کا اعتراض پھر دہرایاکہ یہ تعلیمیں توپہلی کتب کے خلاف ہیں.اورفرمایاکہ یہ اختلاف سطحی ہے.ہرزمانہ کے مطابق کلام اترتا ہے.پھر بتایاکہ اس جواب کو سن کر کفار پینترہ بدلتے ہیں.اورکہتے ہیں یہ پہلی کتب کی نقل ہے.اس کا جواب دیااورثابت کیا کہ نقل کااعتراض بالکل خلاف عقل ہے.پھرہدایت کے سلسلہ میں بتایا کہ بے شک بعض لو گ اس مذہب سے مرتد بھی ہوتے ہیں.لیکن ان کا مرتد ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ قرآن کریم نے یقین کامل پیدا نہیں کیا.کیونکہ یہ امر تب ثابت ہوتا اگر ایسے لوگوں کاارتدادکسی دلیل کی بناء پر ہو.جبکہ دنیوی غرض سے انحراف ہو توارتداد مرتد کاگند ثابت کرتا ہےنہ کہ تعلیم کی کمزوری.پھر بتایاکہ مؤمنوں کے لئے اب حکومت کرنے کا وقت آگیاہے اورقرآنی بشارات اب ان کے حق میں پوری ہونے کو ہیں.ایک زبردست جنگ کفرو اسلام میں ہونےوالی ہے.اس میں ہرایک کو اس کے ایمان کے مطابق
Page 11
بدلامل جائے گا.پھر صاف لفظو ں میں مکہ والوں کی تباہی کی خبردی اوربتایاکہ مکہ والوں کی حکومت جاتی رہے گی.پھررحمت کے مضمون کو الگ کرکے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کس طرح بنی نوع انسان کے لئے ظاہر ی رحمت بھی ہے کہ خلاف عقل رسوم سے انہیں بچاتا ہے.پھر حضرت ابراہیم جومکہ والوں کے جد امجد تھے.ان کی یاد دلائی کہ دیکھو وہ خدا تعالیٰ کافرمانبردار تھا تم بھی اسی کے نقش قدم پر چلو اوراس کی پیروی کروجو ابراہیمی سنت پر ہے.پھر یہودو مسیحی لوگوں کو مخاطب کیا اورفرمایا کہ تم نے بھی دین کو بدل دیا ہے.تم بھی اپنی اصلاح کر واورجو آرام کے سامان خدا تعالیٰ نے دیئے ہیں ان سے گمراہی میں ترقی نہ کرو.آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی کہ اب تیر ی تبلیغ کادائرہ وسیع ہوکر یہود ونصاریٰ کو بھی گھیرنے والا ہے اس کے بارہ میں ہم کچھ ہدایات ابھی سے دےدیتے ہیں.پھر بتایاکہ اب تک تومکہ والے ظلم کرتے تھے.آئندہ یہود و نصاریٰ بھی ظلم شروع کریں گے.اس وقت بھی رحم کرنا اورصبر سے کام لینا.ہاں جب خدا تعالیٰ سزادیناچاہے توان کی تباہی پر غم بھی نہ کرناا ورساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہود و نصاریٰ سے جومقابلہ ہوگا اس میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰۱ (میں)اللہ (تعالیٰ) کانام لے کر (شروع کرتاہوں)جوبے حد کرم کرنے والا (اور)بار بار رحم کرنے والا ہے.اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ۠١ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا (اے منکرو)اللہ (تعالیٰ)کاحکم آگیاہے اس لئے (اب )تم اس کے جلد آنے کامطالبہ نہ کرووہ پاک (ذات) يُشْرِكُوْنَ۰۰۲ ہے اورجن چیزوں کو وہ (لوگ)شریک قرار دیتے ہیں اس سے بہت بالاہے.حلّ لغات.فَلَاتَسْتَعْجِلُوْہُ:اِسْتَعْجَلَہٗ کے معنے ہیں طَلَبَ عَجَلَتَہُ وَلَمْ یَصْبِرْاِلٰی وَقْتِہِ.کسی
Page 12
کام کے لئے خواہش کی کہ وہ وقت سے پہلے ہوجائے.اِسْتَعْجَلَ فُلَانًا:سَبَقَہٗ وَتَقَدَّمَہٗ.فلاں شخص سے آگے نکل گیا.مَرَّفُلَانٌ یَسْتَعْجِلُ اَیْ یُکَلِّفُ نَفْسَہُ العجَلۃَ.یعنی اپنی طبیعت پر زورڈال کر تیزی سے چلا.(اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت ۱۲.اِسْتَعْجَلَہُ حَثَّہُ.اسے کام پر آمادہ کیا.اَمَرَہُ اَنْ یُعجِّلَ.اسے جلدی کرنے کے لئے کہا.اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ۠ کے معنے ہوں گے کہ اللہ کے عذاب کے جلد آنے کامطالبہ نہ کرو.سُبْحٰنَهٗ اوریُشْرِکُوْنَ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۱۹.سُـبْحَانَ اللہِ اَیْ أُبَرِّیُٔ اللہَ مِنَ السُّوْءِ بَرَاءَ ۃً.سبحان کے معنی عیوب سے پاک سمجھنے اور پاک کرنے کے ہیں (اقرب) یُشْرِکُوْنَ اَشْرَکَ کا فعل مضارع ہے جس کے معنی ہیں جَعَلَ لَہُ شَرِیْکًا.کسی کو کسی کا شریک قرار دیا اور حصہ دار ٹھہرایا.(اقرب) تفسیر.پہلی سور ۃ میں کہاتھا کہ اِنَّ السَّاعَۃَ لَاٰتِیَۃٌ.اب فرمایا کہ اب تو اس ساعت کو آیاہواہی سمجھو.یعنی وہ اب دروا زے پر ہے.قرآن کے محاورہ کے مطابق ماضی یقین اورقربِ وقوع کے اظہار کے لئے بھی آتی ہے اوراس جگہ یہی مراد ہے.اَمْرُاللّٰہِ کے دو معنے اَمْرُاللّٰہِ.امراللہ کے دومعنے ہوسکتے ہیں.(۱)وہ وعید جس کا پچھلی سورتوں میں ذکر تھا.(۲)وہ وعدہ جس کی طرف وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ میں اشارہ کیاگیاتھا.اس جگہ دونوں معنے چسپاں ہوتے ہیں.اوربتایاگیاہے کہ کفار کی سزا اورمومنوں کی کامل اورآزاد تربیت کرنے کا وقت آگیا ہے.فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ میں دو امور کی طرف اشارہ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ.اس میں بھی دونوں امور کی طرف اشارہ ہے.(۱)عذاب مانگنے میں اب جلدی نہ کرو.و ہ تواب تمہارے دروازوں پرہے.(۲)تم مسلمانوں کے نئے نظام کاباربار مطالبہ کرتے تھے لو وہ اب آپہنچا.اب اس کی نسبت جلد آنے کامطالبہ نہ کرو کہ وہ مطالبہ پوراہونے لگاہے.ترتیب سور مضامین کے لحاظ سےہے اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ سورۃ سورئہ حجرکی پیشگوئی کی وضاحت کرتی ہے اوراس کامضمون اس کے مضمون کے تسلسل میں ہے اوراس کااس مقام پر رکھاجانابتاتا ہے کہ قرآن کریم کی سورتیں مضمون کے لحاظ سے آگے پیچھے رکھی گئی ہیں نہ کہ لمبائی اورچھوٹائی کے لحاظ سے.جیسا کہ بعض
Page 14
سُبْحٰنَهٗ کہہ کر اس حکم پرکامیاب طورپر عمل ہوجانے کی خبر دی.کیونکہ ان الفاظ میں بتایاگیا ہے.کہ ہم نے جوکہاتھا کہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی کو اب ظاہر کرو.اب تجھے یہ بتاتے ہیں کہ تیری یہ کوشش ناکام نہ رہے گی.بلکہ عنقریب تیرے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی سبوحیت یعنی اس کا سب اعتراضات سے پاک ہوناثابت ہوجائے گا.گویا اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ کہہ کر خدا تعالیٰ پر جو اِنَّ السَّاعَۃَ لَاٰتِیَۃٌ کے وعدہ کے پورانہ ہونے کی صورت میں اعتراض ہوسکتاتھا اُسے دور کیا اورسُبْحَانَہٗ کہہ کر اس اعتراض کودورکیاجوسَبِّحْ کے حکم کے پورانہ ہونے کی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑسکتاتھا.وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.یعنی ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ بالاہے.ان کاشرک اس کی تدابیر میں روک نہیں بن سکتا اوران کے معبود اس کے فیصلہ کونہیں مٹاسکتے.خدائی کلام اور بندے کے افتراء میں فرق اس آیت سے خدائی کلام اوربندے کے افتراء میں خوب فرق معلوم ہو جاتا ہے.دنیاکے لوگ جتھے پرزوردیاکرتے ہیں اورکہاکرتے ہیں کہ ہم اپنے جتھے کو بلائیں گے.اور اکیلے ہوں تواس کی شکایت کرتے ہیں اورکہتے ہیں کیاکریں اکیلے ہیںکوئی ساتھی نہیںورنہ بتادیتے.بہاءاللہ نے بھی جو الوہیت کامدعی تھااپنے فرید ہونے کارونا روکر اپنی کمزوری کااقرار کیا ہے.(المبین از بہاء اللہ ص ۲۰۶) اس کے مقابلہ میں سچا خداہمیشہ اپنے ایک ہونے پر زوردیتاہے.اورخداکے لئے جتھاقراردینے والوں پر ناراض ہوتاہے.بیٹابیٹیوں یادرباریوں کے ماننے یادرباری کہنے والوں پر اظہار غضب فرماتا ہے.یہی وہ مقام ہے جو حقیقی اوراصلی طاقت و شوکت کا مقام ہے.جھوٹے مدعی اپنے اکیلا ہونے کا ماتم کرتے ہیں سچاخدااپنے اکیلے ہونے کو اپنی بڑائی کے ثبوت میں پیش کرتا ہے.يُنَزِّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ وہ فرشتوںکو اپنے ان بندوںپر جنہیں وہ پسند کرتاہے (اپنی )خاص وحی یعنی یہ حکم دے کر اتارتاہے کہ (لوگوںکو) عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ آگاہ کرو کہ بات یہی (درست )ہے کہ میرے سواکوئی بھی (سچا)معبود نہیں ہے اس لئے تم مجھے (ہی)اپنے
Page 15
اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ۰۰۳ بچائوکاذریعہ بنائو.حل لغات.الرُّوْحُ اَلرُّوْحُ کے لئے دیکھو حجرآیت نمبر۳۰.الرُّوْحُ مَابِہِ حَیَاۃُ الْاَنْفُسِ.وہ چیز جس کے ذریعہ نفوس زندہ رہتے ہیں.یعنی جس کو زندگی کہتے ہیں.الْوَحْیُ الہام.جِبْرِیْلُ جبرائیل.اَلنَّفْخُ پھونک.اَمْرُالنُّبُوَّۃِ، امرنبوت.وَحُکْمُ اللہِ وَاَمْرُہُ.خدا تعالیٰ کا فیصلہ اوراس کاحکم.تُطْلَقُ الْاَرْوَاحُ عَلٰی مَایُقَابِلُ الْاَجْسَادَ جسم کے مقابل چیز کوبھی روح کہتے ہیں.(جو انسان میں جسم کے علاوہ موجود ہے )وَعِنْدَ اَصْحَابِ الْکِیْمِیَا عَلَی الْمِیَاہِ الْمُقَطَّرۃِ مِنَ الْاَدْوِیَۃِ.کیمیا والوں کے نزدیک دوائیوںکے عرق کوبھی روح کہتے ہیں.(لیکن یہ فن کی ناواقفی کی وجہ سے لکھا ہے کیمسٹری والے عرق کو روح نہیں کہتے.بلکہ یاتو تیل والی ادویہ کاوہ حصہ جو عرق پر آجاتاہے اسے روح کہتے ہیں جیسے روح گلا ب یا پھر عرق کو باربار کشید کرکے اس کی تیز خوشبوکو عرق سے الگ کرلینے پر اسے روح کہتے ہیں جیسے روح کیوڑہ) (اقرب) جبرائیل کو جو صاحب اقرب الموارد نے روح لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جبرائیل کو روح کہاگیاہے اس لئے انہوں نے روح کے معنے جبرائیل قراردے دیئے.جبرائیل کو روح کے نام سے پکارے جانے کی وجہ حالانکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بعض دفعہ مسبب کانام سبب کو دے دیاجاتاہے اوراسی لحاظ سے جبرائیل کو روح کہا گیا ہے.کیونکہ وہ روح یعنی کلام الٰہی کو لاتاہے.غر ض روح کے معنے جبریل نہیں بلکہ استعارۃً وحی لانے والے فرشتے کو کہتے ہیں.اصل میں روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کسی کو حیا ت ممتاز ملے.پس وہ روح جو حیوان کو باقی چیزوں سے ممتاز کررہی ہے.اوروہ روح جس کے ساتھ انسان باقی حیوانوں سے ممتازہوتاہے ان دونوں پر لفظ روح کااطلاق ہوتاہے.یاوہ روح جوانسان کو باخدابنادیتی ہے پس کلام الٰہی بھی ایک روح ہے جو انسان کو نئی زندگی بخشتاہے.اَنْذِرُوْا.اَنْذِرُوْااَنْذَرَسے امر کا جمع کا صیغہ ہے.اَنْذَرَکے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۳.اَنْذِرْ اَنْذَرَ کا صیغۂ امر ہے.اس کی مصدر اِنْذَارٌ ہے اور الفاظ نَذْرٌ، نُذْرٌ، نُذُرٌ اور نَذِیرٌ بھی اس معنی میں آتے ہیں.کہتے ہیں اَنْذَرَہٗ بِالْاَمْرِ.أَعْلَمَہُ وَحَذَّرَہُ مِنْ عَوَاقِبِہِ قَبْلَ حُلُوْلِہٖ یعنی کسی امر کی حقیقت سے اسے آگاہ کیا.اور اس امر کے نتائج کے ظاہر ہونے سے پہلے اسے ہوشیار کر دیا اور کہتے ہیں اَنْذَرَہٗ: خَوَّفَہٗ فِیْ اِبْلَاغِہٖ
Page 16
یُقَالُ اَنْذَرْتُ الْقَوْمَ سَیْرَ الْعَدُوِّ اِلَیْھِمْ فَنَذِرُوْا یعنی اَنْذَرَہُ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خبر پہنچاتے ہوئے خوب ہوشیار کیا چنانچہ جب کہتے ہیں اَنْذَرْتُ الْقَوْمَ سَیْرَ الْعَدُوِّ تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں نے قوم کو دشمن کی پیش قدمی سے خوب ہوشیار کیا.اور اس کا فعل لازم یا مطاوع نذر ہے جس کے معنی ہیں وہ ہوشیار ہو گیا.(اقرب) تفسیر.روح سے مراد دنیا کو زندہ کرنے والا کلام اور امر نبوت بِالرُّوْحِ.روح سے مراد دنیا کو زندہ کرنے والا کلام ہے.امر نبوت کو بھی روح کہتے ہیں.نبیوں اورماموروں کا کلام چونکہ دنیا کے لئے زندگی بخش ہوتا ہے اس لئے اُسے روح قرار دیاجاتاہے.اَنْ اَنْذِرُوْا میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت میں وحی نبوت کا ذکرہے.وحی کی دو قسمیں وحی دو قسم کی ہوتی ہے.ایک صرف انسان کے اپنے نفس کے لئے.اس وحی کوظاہر کرنے کا حکم نہیں دیاجاتا.گواجاز ت ہوتی ہے کہ انسان اس کا اظہار کردے.دوسری وحی بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے اورپھیلانے کاحکم دیاجاتاہے.بلکہ اس کے نہ پھیلانے کو جرم قرار دیاجاتاہے یہ دوسری قسم کی وحی نبیوں کی وحی ہوتی ہے.اس جگہ اَنْذِرُوْا کہہ کر اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جس وحی کااس جگہ ذکر کررہے ہیں.وہ وحی نبوت ہے.مِنْ اَمْرِہٖ میں چار باتوں کی طرف اشارہ مِنْ اَمْرِہٖ.ان الفاظ سے ایک تویہ بتایا ہے کہ ملائکہ خود کلام نازل نہیں کرسکتے.بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں.اوراسی کابھیجا ہواکلام لاتے ہیں.دوسرے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس جگہ اس روح یعنی کلام الٰہی کا ذکر ہے جو مِن اَمراللہ ہوتاہے.یعنی اس میں خدا تعالیٰ کے اوامرو نواہی کا ذکر ہوتا ہے ان معنوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ وحی نبوت کا ذکر ہے.مِنْ اَمْرِہٖ سے اَتٰی اَمْرُاللہِ کی طرف بھی اشارہ کیا گیاہے.اوربتایا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے اَتٰی اَمْرُاللہِ.یہ سنت ہماری سب نبیوں کے متعلق ہے.ہم ان میں سے ہر اک کی طر ف فرشتوں کو وحی دے کر بھیجتے ہیں.اوراس میں ہمارے امر کابیان ہوتاہے یعنی کفار کی ہلاکت اورمؤمنوں کی ترقی کا.گویا کوئی نبی نہیں آتا کہ اس کے ذریعہ سے ایک قوم کی ہلاکت اوردوسری قوم کی ترقی کی خبرنہ دی گئی ہو.مِنْ اَمْرِہٖ میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہرنبی کامانناضروری ہوتاہے.کیونکہ وحی نبوت امر الٰہی پر مشتمل ہوتی ہے پس ہررسول کا انکار اس کا ہی انکار نہیں.بلکہ خدا تعالیٰ کا انکارہوتاہے جس نے اس پر وحی کی.مِنْ عِبَادِہٖ سے مراد عابد بندے ہیں عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ میں عِبَادِہٖ سے مراد اللہ تعالیٰ کے
Page 17
عابد بندے ہیں نہ کہ ہرانسان.اوراس طرف اشار ہ ہے کہ گونبوت وہبی ہے.مگر اس کانزول عباداللہ پرہی ہوتاہے.گویا یہ وہب ایک کسب کے ساتھ وابستہ ہے.اوریہ وہب مشروط ہے عبد ہونے کے ساتھ.اِن موہبتوں میں سے نہیں جو بلا قید ہرایک کومل سکتی ہیں.مِنْ عِبَادِهٖۤ ہنے سے تین باتوں کی طرف اشارہ مِنْ عِبَادِہٖ سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وحی نبوت صرف موحد بندوں پر نازل ہوتی رہی ہے جو توحید کی دلیل ہے.اگر شرک بھی جائز ہوتا.توکیوں نہ کوئی نبی ایسا بھی پایاجاتاجو خالص اللہ تعالیٰ کاعبد نہ ہوتا.بلکہ دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرلیاکرتا.توحید کایہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آج تک ایک بھی نبی نہیں ہواجومشرک ہو.پھر نہ معلوم مشرک اپنے عقیدہ کی بنیاد کس دلیل پر رکھتے ہیں.عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ بندوں کی مرضی کے مطابق نہیں کرتا.بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کرتاہے.اس لئے بندوں کا اس سے مختلف الخیال ہوناضروری ہے.اورجب نبی خدا کا منتخب کیا ہواہوتا ہے.توکفار کا یہ اعتراض کہ اس کے خیال قومی خیالات سے مختلف کیوںہیں کم عقلی کی علامت ہے.کلام الٰہی ہمیشہ آہستہ آہستہ اترتا ہے يُنَزِّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةَ.تنزیل کے ایک معنے آہستہ آہستہ اُتارنے کے ہوتے ہیں.اس جگہ یہی معنے مراد ہیں اوربتایا ہے کہ کلام الٰہی ہمیشہ اورہرنبی پر آہستہ آہستہ اترتاہے.مسیحیوں کے اعتراض کا ردّ پس یہ اعتراض جو رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگوں کی طرف سے خصوصاً مسیحیوں کی طرف سے کیاجاتا ہے کہ اس کاتھوڑاتھوڑاکرکے اُترنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی کلام ہے اورضرورت کے مطابق تصنیف کرلیا جاتاتھا.ان کی سنّت الٰہیہ سے ناواقفیت کی علامت ہے.کیونکہ کون سا نبی ہے جس نے ایک وقت میں ہی ساری کتاب لاکر دنیاکودے دی ہے.موسیٰ کے صحف.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب اس ا مر پر شاہد ہیںکہ تعلیم آہستہ آہستہ ایک لمبے عرصہ میں دنیا کودی گئی.اگراس طرح تعلیم کادنیا کے سامنے پیش کرنا قابل اعتراض ہے تو یہ اعتراض حضر ت موسیٰ ؑاور حضرت عیسیٰ ؑ پر بھی وارد ہوتاہے.لیکن حق یہ ہے کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے.جوتعلیم دنیا کے رائج الوقت خیال کے خلا ف ہو اوراس کو مٹاکر اوامر الٰہی کو رائج کرنے کے لئے آئے.اس کاآہستہ آہستہ اترنا ضروری ہے.تالوگ اس پر اچھی طرح عمل کرسکیں اورتاوہ ان کے دماغوں میں راسخ ہوجائے.اسی کی طرف اشارہ ہے سورۃ فرقان کی اس آیت میں کہ وَ قَالَ الَّذِيْنَ
Page 18
كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً١ۛۚ كَذٰلِكَ١ۛۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ(الفرقان:۳۳)یعنی کافر کہتے ہیں کہ کیوں سب قرآن اس پر ایک ہی دفعہ نہیں اترا.یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کاکلام نہیں.بلکہ محمدؐ رسو ل اللہ حسب موقعہ اسے تصنیف کرلیتے ہیں.قرآن کریم کو آہستہ آہستہ اتارنے کی حکمت فرماتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ قرآن ایک ہی دفعہ نہیں اُترا.مگراس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح تیرے دل کو ثبات اورایمان بخشناچاہتے ہیں.یعنی تواورتیرے مؤمن اس کے مطالب کو عملی جامہ پہنا کر اس کے معانی سے خوب آگاہ ہوتے جائو اوراس لئے بھی کہ اگر پہلے ایک پیشگوئی بیان کی جائے.پھر جب وہ پوری ہوجائے اوراس کا ذکر بعد کی وحی میں کیاجائے توایمان بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے.اوریہ طریق بیان بعد میں آنے والے لوگوں کے ایمان کی زیادتی کابھی موجب ہوتاہے.لیکن اگر کلام الٰہی میں پیشگوئیوں کاتوذکرہو.لیکن ان کے پوراہونے کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو.تواس وقت کے لوگ بھی اتنافائدہ نہیں اٹھاتے.اوربعد کے لوگوں کے لئے بھی وہ کلام کافی نہیں ہوتا.بلکہ دوسری کتب کے وہ محتا ج رہتے ہیں.مِنْ اَمْرِهٖ میں مِن تبعیضیہ کے لحاظ سے معنی مِنْ اَمْرِهٖ میں مِنْ تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے اورمطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے حکم ایک ہی وقت میں کسی ایک نبی پر نازل نہیں کئے.بلکہ ہرزمانہ میں ضرورت کے مطابق اپنے احکام مختلف انبیاء کی معرفت نازل کئے ہیں.پس یہ اعتراض کہ پہلے نبیوں کے بعد اس کی کیا ضرورت ہے غلط ہے.جس طرح پہلے نبی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت تھی.اسی طرح سابق نبیوں کے بعد اس نبی کی ضرورت ہے.لا الٰہ الَّا اللہ دینی تعلیمات کا خلاصہ ہے اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ.یہ تمام دینی تعلیمات کا خلاصہ ہے.نبیوں کی تعلیم جزئیات میں مختلف رہی ہے.مگرایک ہی اصل سب کی تعلیم میں کارفرماتھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اوردین کاخلاصہ یہی تعلیم ہے.ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوہریرہؓ سے فرمایاکہ جاجو ملے اُس سے کہہ دے مَنْ قَالَ لَااِلٰہَ اِلَّااللّٰہُ دَخَلَ الْجَنَّۃَ.جس نے لَااِلٰہَ اِلَّااللہُ کہاداخل جنت ہوگیا.(مسلم کتاب الایمان باب الدلیل علی انہ من مات علی التوحید دخل الجنة)انہیں سب سے پہلے حضرت عمرؓ ملے اورانہوں نے انہیں روکا اورآنحضرت صلعم کی خدمت میں لائے.اورآپ سے پوچھا کہ کیا ابوہریرہ جو کہتے ہیںوہ درست ہے ؟ آپؐ نے فرمایا.ہاں درست ہے.آپ نے فرمایا.یارسول اللہ اگر اس طرح اعلان ہوا تو فَاِنِّیْ اَخْشٰی اَنْ یَّتَّکِلَ النَّاسُ عَلَیْہَا یعنی لو گ یہ کہنے لگ جائیں گے کہ بس لاالہ الااللہ کہہ لیا اب کسی عمل کی ضرورت نہیں.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا رہنے دو.اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپؐ نے اس کوضروری نہ سمجھا.
Page 19
بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو اعلان کرناتھا ہوچکا.جواس کامفہوم سمجھتے تھے ان کومعلوم ہوگیا.نااہلوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں.اس حکم کے اہل جو سمجھتے ہیں کہ لاالہ الااللہ میں سب احکام شامل ہیں وہ خود اس کی مناسب تشریح کےساتھ سب کو پہنچا دیں گے.اتَّقٰی کے معنے اِتَّقُوْنِ وَقٰی یَقِیْ سے باب افتعال کاصیغہ ہے اوراس کے معنے ہیں.اپنی حفاظت کاذریعہ کسی کو بنانا.پس اِتَّقُوْنِ کے معنے ہیں.کہ مجھے ہی اپنی حفاظت اوربچائو کاذریعہ بنائو.یہ مطلب نہیں کہ مجھ سے اس طرح ڈروجس طرح نقصان رساں چیزوں سے ڈرتے ہیں.کیونکہ خدا تعالیٰ توخود اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اوران سے محبت کرتاہے.خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ١ؕ تَعٰلٰى اس نے آسمانوںاورزمین کو حق(و حکمت)کے ساتھ پیدا کیاہے اورجن چیزوں کو (یہ لوگ اس کا )شریک عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۰۰۴ ٹھہراتے ہیں وہ اس سے بہت بالاہے.حلّ لُغَات.اَلْـحَقُّ کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر۱۵.اَلْحَقُّ حَقٌّ کا مصدر ہے.اور حَقَّہٗ حَقًّا کے معنے ہیں غَلَبَہٗ عَلَی الْحَقِّ.حق کی وجہ سے اس پر غالب آیا.وَالْاَمْرَ: اَثْبَتَہٗ وَاَوْجَبَہٗ.کسی امر کو ثابت کیا اور واجب کیا.کَانَ عَلٰی یَقِیْنٍ مِنْہُ.کسی معاملہ پر یقین سے قائم تھا.اَلْخَبَرَ: وَقَفَ عَلٰی حَقِیْقَتِہِ اور حَقَّ الْخَبَرَ کے معنے ہوں گے اس کی حقیقت سے آگاہ ہوا اور اَلْحَقُّ کے معنے ہیں ضدُّ الْبَاطِلِ سچ.اَ لْاَمْرُ الْمَقْضِیُّ فیصلہ شدہ بات.اَلْعَدْلُ.عدل.اَلمِلْکُ.ملکیت.الْمَوْجُوْدُ الثَّابِتُ.موجودو قائم.اَ لْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ.یقین.اَلْمَوْتُ.موت اَلْـحَزْمُ دانائی.(اقرب) تفسیر.حق کے دو معنی بِالحقِّ (۱)ہراک کاحق مقررکردیا ہے یعنی کچھ کام کاحصہ آسمان کے سپرد کردیااور کچھ زمین کے سپرد کردیا.دونوں مل کرنتائج پیداکرتے ہیں.(۲)یعنی دونوں کو حکمت کے ماتحت اس لئے پیدا کیا تا انسان کی توجہ خدا کی طرف پھر ے.اورانسان سمجھے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی فی ذاتہٖ کامل نہیں.آسمان اپنے کام کی تکمیل میں زمین کا محتاج ہے اورزمین آسمان کی
Page 20
دست نگر.صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے کام لے رہاہے.تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.فرمایاکہ جوانسان آسمان اور زمین کو بِالْحَقّ نہیں مانتا.وہ لازماًمشرک بنتا ہے.کیونکہ کوئی عقلمند یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جہان کوخدا نے بنایا ہے مگراس میں مقصد کوئی مقرر نہیں کیا.کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے توضرور اس کاکوئی مقصد ہے.اوراگر اس کاکوئی مقصد نہیںتویقیناًخدا نے نہیں بنایا.بلکہ یہ خودبخود ہے جس کے یہ معنے ہیں کہ ذرّہ ذرّہ خدا کاشریک ہے.دوسرے معنے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ زمین و آسمان کابناناحق کے ساتھ ہے.یعنی ان کا مادہ ہماراپیداکردہ ہے.اس لئے اس میں تصرف کاہم کو حق حاصل ہے.اس میں ان لوگوں کاردّ ہے جو ایک طرف خدا تعالیٰ کو مادہ کاخالق نہیں سمجھتے.دوسری طرف اس کی ترکیب کا فاعل خدا تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں.(ستیارتھ پرکاش از سوامی دیانند اردو ترجمہ کوریمل داس جی باب ۸ ص ۲۷۴)حالانکہ جو خالق نہیں اُسے کیا حق حاصل ہے کہ اس میں تصرف کرے اورایک موجود بالذات کو اپنے حکم کے نیچے لائے یہ توظلم ہوجاتا ہے.اورنیز یہ عقید ہ مشرکانہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ان گنت وجودوں کو ازلی قراردیاگیا ہے.خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ۰۰۵ اس نے انسان کو ایک حقیر نطفہ سے پیدا کیاہے پھر (اس کے باوجود )وہ اچانک کھلم کھلا جھگڑنے والا بن جاتا ہے.حلّ لُغَا ت.نُطْفَۃٌ.النُّطْفَۃُ کے معنے ہیں.اَلْمَاءُ الصَّافِیْ قَلَّ اَوْ کَثُرَ.صاف وشفاف پانی خواہ تھوڑاہویازیادہ.یُقَالُ سَقَانِیْ نُطْفَۃً عَذَبَۃً چنانچہ سَقَانِیْ نُطْفَۃً عَذْبَۃً کامحاورہ بول کر یہ مراد لیتے ہیں کہ اس نے مجھے صاف شیریں پانی پلایا.وَقِیْلَ قَلِیْلُ مَاءٍ یَبْقٰی فِی دلْوٍ اَوْقِربَۃٍ.بعض نے نطفہ کے معنے اس تھوڑے سے پانی کے کئے ہیں جوڈول یا مشکیزہ کو خالی کرتے وقت باقی رہ جاتا ہے.مَاءُ الرَّجُلِ وَالْمَرأَۃِ.مرد یاعورت کی منی.اَلْبَحْرُ.نطفہ کے ایک معنے سمند رکے بھی ہیں.ا س کی جمع نِطَافٌ اورنُطَفٌ آتی ہے.(اقرب) خَصِیْمٌ:خَصِیْمٌ خَصَمَ (یَخْصِمُ خَصْمًا)سے صفت مشبّہ ہے اورخَصَمَہُ کے معنے ہیں غَلَبَہُ فیِ الْخُصُوْمَۃِ.اس پر جھگڑے میں غالب آیا.اَلْخَصِیْمُ.اَلْمُخَاصِمُ.خصیم کے معنے ہیں.جھگڑنے والا.اس کی جمع خُصَمَاءٌ آتی ہے (اقرب) تفسیر.آیتخَلَقَ الْاِنْسَانَ الخ میں تین باتوں کی طرف اشارہ اس آیت میں یہ بتایا
Page 21
ہے کہ زمین وآسمان کوایک خاص نظام کے ماتحت پیداکرکے ہم نے انسان کوبنایا.اوراپنے حق کی بناء پر اس کے لئے ہدایت نامے نازل کئے.مگر باوجود اس کے کہ ہم نے اُسے ایک حقیر مادہ سے پیداکرکے اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت عطا کی.وہ اُلٹاہمارے حقوق کے متعلق بحث کرنے لگتا ہے.کوئی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عدم سے وجود کس طرح پیدا کیا اس لئے دنیا خود بخود بنی ہے.کوئی کہتا ہے خدا نے مادہ نہیں بنایا.بلکہ یونہی جبراً اس پر تصر ف کرلیا ہے کوئی کہتا ہے کہ خدا کو کیاحق حاصل ہے کہ میرے لئے ہدایت نامہ جاری کرے.میں آزا دہوں.میں اپنے لئے خود قانون بنائوں گا.غرض اس کے احسا ن کاانکارکرنے لگتا ہے اوراپنے آپ کو آزاد بتاتا ہے.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خود تو ایک حقیر ماد ہ سے پیدا ہونے کے باوجو د اپنے آپ کواتنابڑاسمجھنے لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے بھی بحث کرنے کو تیارہو جاتا ہے.لیکن دوسری طرف نبیوں پر اعتراض کرتا ہے اورنہیں سمجھتا کہ جس خدا نے ایک حقیر نطفہ سے پیداکرکے ایک سمجھد ار انسان بنادیا جو الٹانافرمان ہوگیا.کیا وہ ایک بظاہر حقیر نظر آنے والے انسان کو آگے ترقی دے کر انسان کامل نہیں بناسکتاکہ تاوہ اس کی فرمانبرداری کرے اور دوسروں سے کرائے.اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خلق زمین و آسمان سے یہ غرض تونہ ہوسکتی تھی کہ ایک نافرمان انسان پیداہو.یقیناً خلق کا مقصد اس سے بالاہوناچاہیے تھا.پھر جب اس مقصد کوپوراکرنے والاانسان دنیا میں آتاہے تولوگوں کوتعجب کیوں ہوتاہے.وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا١ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا اور(نیز)چارپایوںکو (پیدا کیا ہے اور)انہیں اس نے ایسابنایا ہے کہ ان میں تمہارے لئے گرمی کاسامان تَاْكُلُوْنَ۪۰۰۶ اور(اوربھی)کئی نفعے ہیں اور تم ان (کے گوشت )کاکچھ حصہ کھاتے ہو.حلّ لُغَات.دِفءٌ.دَفِیءَ( یَدْفَأُ.دَفَأًودَفُؤَ.یَدْفُوءُ.دَفَاءَۃً) مِنَ الْبَرَدِ کے معنے ہیں.تَسَخَّنَ وَوجَدَ الْـحَرَّ.گرم ہوااور گرمی کو محسوس کیا.اَلدِّفْءُ.نَقِیْضُ حِدَّۃِالْبَرْدِ.گرمی.الدِّفْءُ مِنَ الْحَائِطِ کِنُّہٗ.دیوار کی پنا ہ.یُقَالُ ’’ اُقْعُدْ فِی دِفْءِ ھٰذَاالْحَائِطِ‘‘ اِیْ کِنِّہِ.چنانچہ اُقْعُدْ فی دِفْ ءِ
Page 22
ھَذَاالْحَائِطِکہہ کر یہ معنے لیتے ہیں کہ اس دیوار کی پناہ اوراوٹ میں بیٹھ.مَااَدْفَأَمِن الْاَصْوافِ والاوْبَارِ.گرم کپڑے.(اقرب) مَنَافِعُ.مَنَافِعُ مَنْفَعَۃٌ کی جمع ہے اورمَنْفَعَۃٌ کے معنے ہیں.اَلنَّفْعُ.نفع.وکُلُّ شَیْءٍ یُنْتَفَعُ بِہِ.ہر وہ چیزجس سے فائدہ اُٹھایاجائے.(اقرب) تفسیر.آیت وَ الْاَنْعَامَ میں انسانی خصومت کا جواب اس آیت میں نہایت لطیف پیرایہ میں انسان کی خصومت کا جواب دیا ہے.فرماتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا.لیکن تم کو آزادی کادعویٰ ہے.حالانکہ خود تم ان چیزوں پر تصرف کرتے ہو جن کو تم نے پیدا نہیں کیااور ان سے خوب فائدہ اُٹھاتے ہو.حتٰی کہ ان کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے اورکہتے ہوکہ انسان اعلیٰ ہے اس لئے اس کی خاطردوسرے جانوروں کوذبح کرنا تک درست ہے.اگر یہ درست ہے کہ اعلیٰ کے لئے ادنیٰ قربان کیاجاسکتا ہے اوراعلیٰ کو ادنیٰ سے کام لینا جائزہے تو ہماری حکومت پر یارسول کی حکومت پر تم کو کیا اعتراض ہے.وہی قانون جو تم ان کے لئے جاری کرتے ہو.اپنے متعلق جاری کرنے کے لئے کیوں تیار نہیں ہوتے.دوسرے معنےا س آیت کے یہ ہیں کہ ایک پہلی آیت یعنی عَلیٰ مَنْ یَّشَآئُ پرجوکفار اعتراض کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے اس حقیر بندہ پر کس طرح کلام نازل کیا.اس کا جواب یہ کہہ کر دیاتھا کہ کیا تم کو ہم نے ایک حقیر نطفہ سے پیداکرکے اعلیٰ مرتبہ تک نہیں پہنچایا.پھراگربعض لوگوںکو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو اگر نبی بنا کر عزت دی.تواس پر تمہارا اعتراض کیونکر درست ہو سکتا ہے.اب اس آیت میں ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیاجو اَنْ اَنْذِرُوْا سے پیداہوسکتا تھا.یعنی یہ کہ ہم توگندے اورکمزورانسان ہیں.اللہ تعالیٰ ہماری طرف توجہ کس طرح کرسکتا ہے.اورفرمایاکہ خدا تعالیٰ تمہارے کھانے پینے کی فکر توکرسکتا ہے.اس میں اس کی شان میں فرق نہیں آتا.لیکن جب وہ تمہاری روحانی غذاکی طرف توجہ کرے توتم کو یہ اعتراض سوجھتا ہےکہ انسان جیسے حقیر وجود کی طرف خدا تعالیٰ کو کلام بھیجنے کی کیاضرورت ہے.تعجب ہے کہ ہمیشہ سے یہ متضاد اعترا ض نبیوں اورنبوت پر ہوتے چلے آئے ہیں.نبیوں کے دشمن ایک طرف تویہ اعتراض کرتے ہیںکہ اُن حقیر لوگوںکو خدا تعالیٰ کیوں چن سکتاتھا.اگرچنتا توکسی بڑے آدمی کو چنتا.دوسری طرف یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے اس کی نسبت یہ خیال بھی نہیں کیاجاسکتاکہ وہ حقیر انسان کی طرف توجہ کرے گااوراس کے لئے الہام بھیجے گا.فلاسفرخصوصاً یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں.حالانکہ
Page 23
دونوں اعتراض غلط ہیں اورمتضاد بھی.کیونکہ ایک اعتراض سے تواپنا بڑاہونا اورنبیوں کا حقیر ہونا ظاہر کیا جاتاہے.اور دوسرے اعتراض میں اپنے حقیر ہونے کااقرار ہوتاہے.پس اصل بات یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانہ سے الہام کے جوئے سے بچنا چاہتے ہیں.آیت مِنْهَا تَاْكُلُوْنَمیںمِنْهَا کو پہلے رکھنے کی وجہ یہ جو فرمایا مِنْھَا تَاْکُلُوْنَ اس میں مِنْهَا کو پہلے رکھا گیا ہے جوتخصیص کے معنے دیتاہے.اس پر یہ اعتراض پڑسکتا ہے کہ کیاانسان اَنعام کے سوادوسری چیزوں کے گوشت نہیں کھاتے یاسبزیاں نہیں کھاتے.اس کا جواب یہ ہے کہ تخصیص کبھی حصر کے مضمون کے اظہار کے لئے آتی ہے اور کبھی یہ بتانے کے لئے کہ اس قسم کی چیزوں میں سے یہ اہم ہے اوراس جگہ پر اس کے یہی معنے ہیں.اورمراد یہ ہے کہ تمہاری بڑی غذ ا انعام کا گوشت یا دودھ گھی ہے.بے شک مرغی شکار وغیرہ بھی انسان کھاتے ہیں.لیکن اہم غذا انعام کاگوشت یادودھ گھی ہے.یاجو بمنزلہ انعام کے ہیں.جیسے نیل گائے یا ہر ن وغیرہ.یہ چیزیں انسانی غذاکا اہم جزو ہیں.اوردوسری اشیاء ان سے اُترکرہیں.اس آیت میں انعام کے دواستعمال توکھول کر بیان فرما دیئے اول گرمی سردی کے اثرات سے بچاتے ہیں.یعنی ان کی کھالیں اوراُون وغیرہ کو تم استعمال کرتے ہو.دوسرے یہ کہ تم ان کاگوشت کھاتے اوردودھ پیتے ہو.تیسرالفظ منافع کا استعمال کیا گیا ہے.اس سے مراد جانوروں کی تجارت بھی ہوسکتی ہے اورنسل کشی بھی.وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ اور(اس کے علاوہ )تمہار ے لئے ان میں ایک(قسم کا )زینت(کاسامان بھی)ہے جب تم (انہیں )چراکرشام کو وَ حِيْنَ تَسْرَحُوْنَ۪۰۰۷ (ان کے تھانوں کی طرف)واپس لاتے ہواورجب تم (انہیں صبح کو )چرنے کے لئے چھوڑتے ہو.حلّ لُغَات.اَلْـجَمَالُ.اَلْـجَمَالُ اَلْـحُسْنُ فِی الْـخَلْقِ وَ الخُلُقِ.جمال ظاہری و باطنی خوبی کوکہتے ہیں (اقرب) اس جگہ جمال سے مرادجمال معنوی ہے یعنی عزت.کیونکہ جس شخص کاگلّہ صبح و شام آتاجاتا ہے وہ لوگوں میں معزز ہوتاہے.
Page 24
تُرِیْحُوْنَ.تُرِیْحُوْنَ اَراحَ سے مضارع جمع مخاطب کاصیغہ ہے اور ارَاحَ الرَّجُلُ (اِرَاحۃً وارَاحًا )کے معنے ہیں رَاحَتْ عَلَیْہ اِبِلُہٗ وغَنَمُہٗ وَمَالُہ وَلَایَکُوْنُ ذَالِکَ اِلَّا بَعْدَالزَّوَالِ.اس کے جانور(اونٹ.بکریاں وغیرہ)شام کو چر کرآگئے.اوراَرَاحَ الْاِبِلَ والغَنمَ کے معنے رَدَّھَااِلی الْمُرَاحِ کے بھی ہیں.یعنی انہیں ان کے تھانوں کی طرف واپس لوٹایا(اقرب)پس تُرِیْحُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ تمہارے پاس تمہارے جانورشام کو چر کرآتے ہیں یاتم شام کو جانورچراکر واپس لاتے ہو.تَسْرَحُوْنَ.تَسْرَحُوْنَ.سَرَحَ (یَسْرَحُ سَرْحًا)سے مضارع جمع مخاطب کاصیغہ ہے.اورسَرَحَ الرَّاعِی الْمَوَاشیَ کے معنے ہیں.اَسَامَھَااَیْ اَرْسَلَھَا تَرْعٰی.جانورکو چرنے کے لئے چھوڑ دیا.(اقرب)پس تَسْرَحُوْنَ کے معنے ہوں گے تم جانوروں کو چرنے کے لئے چھوڑتے ہو.تفسیر.یعنی یہ جانو ر تمہا ری عزت اوربڑائی کاموجب بھی ہوتے ہیں.تم فخر کرتے ہو کہ میرے پاس اس قدر بھینسیں ہیں.اس قدر گائیں گھوڑے اونٹ بکریاں ہیں.غرض ان کو اپنی عزت کا ذریعہ بناتے ہو.پھر سوچوتو سہی کہ تم اپنی چیزوں کو جو تمہاری مخلوق بھی نہیں اپنے لئے جمال کاموجب بناتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ خیا ل کرتے ہو کہ انسان کو پیداکرکے وہ اسے یوں ہی چھو ڑ دے.حتّٰی کہ وہ اس کی سبوحیت کی بجائے اس پر اعتراض کرے اور بجائے اس کے کہ اس کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی اعلیٰ شان ظاہر ہو اس کی پیدائش موجب اعتراض بن جائے.تم کیوں خیا ل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ بھی یہی چاہے گاکہ اس کی مخلوق اس کے لئے جمال کاموجب ہو یعنی اعلیٰ اخلاق اوردین والی ہو.جس کودیکھ کر انسان محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اعلیٰ مخلوق پیداکی ہے.آیت میں شام کو جانوروں کے آنے کا ذکر ان کو صبح چرنے کے لئے چھوڑنے سے پہلے کرنے کی وجہ یہاں تُرِیْحُوْنَ یعنی شام کو جانوروں کے آنے کا ذکر پہلے کیاگیا ہے اورتَسْرَحُوْنَ یعنی صبح کو انہیں چرنے کے لئے بھیجنے کا ذکر بعد میں کیاگیا ہے.حالانکہ جانو ر پہلے گھر سے جاتاہے اورپھر شام کو واپس آتاہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ جمال کا ذکر ہے اورجانوروں کے صبح گھر سے نکلنے کی نسبت شام کو گھر آنے کی حالت میں جمال زیادہ ہوتاہے.کیونکہ شام کو کھلا پھرنے اورپیٹ بھر کرگھاس کھالینے کے بعد وہ تروتازہ نظر آتے ہیں.نیز اس لئے بھی کہ صبح جب جانور جاتے ہیں توانسان کے دل میں خطر ہ ہوتاہے کہ کوئی جانور کھویا نہ جائے.یاکوئی درندہ اُسے نہ پھاڑ کھائے.مگر جب شام کو جانورصحیح سلامت گھر کی طرف لوٹتے ہیں توانسان کادل مطمئن ہو جاتا ہے اوروہ ان کو دیکھ کر
Page 25
اپنے اند ر فخر محسوس کرتاہے.وَ تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ اورو ہ تمہارے بوجھ اُٹھا کر اس (دور کے)شہر تک بھی لے جاتے ہیں جہاں تک تم اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے الْاَنْفُسِ١ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌۙ۰۰۸ بغیر نہیں لے جاسکتے.تمہارا رب یقیناً (تم پر)نہایت شفقت کر نے والا (اور)بار بار رحم کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.شِقّ شِقٌّکے معنے ہیں اَلْمَشَقَّۃُ.مشقت.(اقرب) رَءُوْفٌ:رَءُوْفٌ رَأَفَ (یَرْأَفُ وَرَ إِفَ یَرْأَفُ رَأْفَۃً)سے مبالغہ کا صیغہ ہے اوررَأَفَ اللہُ بِکَ کے معنے ہیں رَحِمَ اَشَدَّالرَّحْمَۃِ.کہ اللہ نے تجھ پر بہت رحمت کی (اقرب) رأفت کے معنے رحم کے ہوتے ہیں.اس کے استعمال کو دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ رأفت محبت والے جذبہ کوکہتے ہیں.رحم کے موجبات کئی ہواکرتے ہیں.لیکن کسی کی تکلیف اوردکھ کو دیکھ کر دل میں جوہمدردی اور محبت پیداہوتی ہے.اُسے رأفۃ کہتے ہیں.اللہ تعالیٰ کے لئے رءوف کے لفظ کے استعمال کا مطلب پس خدا تعالیٰ کے رء وف ہونے کے یہ معنے ہیں کہ وہ دکھو ں کونہیں دیکھ سکتا.اس لئے اس نے مخلوق کوتکلیف سے بچانے کے لئے ہرقسم کی آرام دہ چیزیں بنادی ہیں.تفسیر.جسمانی سفر کا ذکر کر کے روحانی سفر کی طرف اشارہ یہ جانور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں اوروہاں لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر تکلیف کے نہیں پہنچ سکتے تھے.یعنی یہ نہ ہوتے تو بوجھ اٹھاکرچلنا پڑتا اورتکلیف میں پڑتے.پھرسوچو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسمانی سفرکے لئے اس قدرسامان سہولت پیداکئے ہیں.توکیوں وہ روحانی سفر کے لئے سامان پیدانہ کرے گا.اور تم ان روحانی سامانوں کو دیکھ کرکیوں یہ کہنے لگ جاتے ہوکہ انسان جیسے حقیر وجود کے لئے خدا تعالیٰ یہ کام کس طرح کرسکتا تھا.تم خدا تعالیٰ کی بڑائی کاراگ اس موقعہ پر محض بہانہ سازی سے الاپتے ہو.لیکن یہ بھول جاتے ہو کہ وہ بڑی شان والا بھی ہے مگر ساتھ رؤوف اوررحیم بھی تو ہے.علو شان والے وجود جب رءوف ورحیم بھی ہوں توکمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں اوراس میں ان کی ہتک نہیں ہوتی بلکہ ان کی شان کااظہار ہوتاہے.
Page 26
وَّ الْخَيْلَ وَ الْبِغَالَ وَ الْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً١ؕ وَ اور(اس نے )گھوڑوں اورخچروں اورگدھو ںکو(بھی )تمہاری سوار ی کے لئے اور(نیز)زینت(وشان )کے لئے يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۰۰۹ (پیدا کیاہے )اور (آئندہ بھی )وہ (تمہارے لئے سوار ی وغیرہ کا مزید سامان)جسے تم (ابھی)نہیں جانتے پیداکریگا.حلّ لُغَات.اَلْـخَیْلاَلْـخَیْلُ جَمَاعَۃُ الْاَفْرَاسِ.گھوڑے.خیل کالفظ جمع ہی استعمال ہوتاہے.اس کامفرد نہیں آتا.(اقرب) البِغَال.اَلْبِغَالُ اَلْبَغْلُ کی جمع ہے اوراَلْبَغْلُ کے معنے ہیں حَیَوَانٌ اَھْلِیٌّ لِلرُّکُوْبِ وَالْحَمْلِ اَ بُوْہُ حِمَارٌوَاُمُّہُ فَرَسٌ.خچر.وَیتَوَسَّعُ فِیْہِ فَیُطْلَقُ عَلٰی کُلِّ حَیَوَانٍ اَ بُوْہٗ مِنْ جِنْسٍ وَاُمُّہُ مِنْ اٰخَرَ.اس جانور پر بھی یہ لفظ اطلاق پاتاہے جس کے ماں اورباپ دومختلف جنسوں سے ہوں یعنی دوغلا.(اقرب) الحَمِیْر.اَلْـحَمِیْرُحِمَارٌ کی جمع ہے اس کے معنے ہیں گدھے.اس کے علاوہ حِمَارٌ کی جمع اَحْمِرَۃٌ وَحُـمُرٌ بھی آتی ہے.(اقرب) تفسیر.زِیْنَۃً.زینت سے یہاں مراد خالی زینت نہیں.کیونکہ پہلے وَ لَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ فرماچکا ہے.اس سے وہ زینت مراد ہے جو لِتَرْکَبُوْھَاکے ساتھ تعلق رکھتی ہے یعنی طاقت.قوت.شوکت اور دبدبہ کا اظہار.گھوڑ ے.خچریں اورگدھے جنگی قوموں کو طاقت کا مظاہر ہ کرنے میں مدد دیتے ہیں اوریہاں زینت سے یہی مراد ہے.زِيْنَةً پر نصب اس لئے آئی ہے.کہ یہ خَلَقَ کامفعول لہٗ ہے.انسانوں کے نفع کے لئے دو قسم کی چیزوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا دو قسم کی چیزیں تمہارے واسطے پیداکی ہیں.(۱)وہ جن سے تم کو غذاملتی ہے تم ان کا گوشت کھاتے اوردودھ پیتے ہو.ان سے گرمی سردی سے بچائو کا ساما ن حاصل کرتے ہو اوروہ تمہارے لئے لوگوں میں عزت و فخر کاموجب ہوتے ہیں.اورپھر و ہ تمہارے بوجھ اٹھاکر دوسرے شہروں تک پہنچاتے ہیں جیسے اونٹ گائے وغیرہ یہ جانور اہلی زندگی میں کام آنے والے ہیں.(۲)دوسری وہ چیزیں ہیں جو تمہاری جنگی اورسیاسی زندگی میں کام آتی ہیں.کیونکہ ان سے جنگ وغیرہ میں
Page 27
کام لیا جاتا ہے.دونو قسم کی اشیاء کی پیدائش کی چھ غرضیں یہ تمام چیزیں چھ غرضوں کے لئے بنائی گئی ہیں.۱.موسموں کے اثرات سے حفاظت کے لئے.۲.غذاکے مہیاکرنے کے لئے.۳.عزت و فخر کے لئے.۴.بوجھ اٹھانے کے لئے.۵.سفر میں سواری کے کام آنے کے لئے.۶.طاقت اورقوت کاموجب بننے کے لئے.جب ان چھ دنیوی اورمادی ضرورتوںکو اللہ تعالیٰ نے پوراکیا ہے.توتم کس طرح خیال کرتے ہو کہ اسی قسم کی چھ روحانی ضرورتوں کے پوراکرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے سامان نہ پیداکئے ہوں گے.دوسرے ان آیات میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تم دوسری مخلوق سے باوجود اس کے خالق نہ ہونے کے ہرطر ح کے کام لیتے ہو.مگر اللہ تعالیٰ جو تمہارامحتاج نہیں اور تم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا.اُسے یہ حق بھی نہیں دیتےکہ تمہاری اصلاح کرکے تم کو ایسا بنائے کہ تم اس کی سبوحیّت اورقدوسیّت کی دلیل اوراس کی بڑائی کے اظہار کا ذریعہ بنو.وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَآىِٕرٌ١ؕ وَ لَوْ شَآءَ اور(تمہیں) سیدھی راہ (کابتانابھی )اللہ(تعالیٰ) ہی کے ذمہ ہے.اور(اس کی ضرورت اس لئے ہے کہ )ان لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَؒ۰۰۱۰ میںسے بعض (راستے )ٹیڑھے (ہوتے )ہیں اوراگر وہ اپنی (ہی)مشیت نافذ کرتا توتم سب کو ہدایت (ہی)دیتا.حلّ لُغَات.اَلْقَصْدُ.اَلْقَصْدُ قَصَدَ کامصدر ہے اورقَصَدَہٗ(وَلَہٗ وَاِلَیْہِ)کے معنے ہیں.اِعْتَزَمَ عَلَیْہِ وتَوَجَّہَ اِلَیْہِ.کسی چیز کا اراد ہ کرلیا اوراس کی طرف گیا.قَصَدَ اِلَیْہِ.اِعْتَمَدَہٗ.اس پر اعتماد کیا.قَصَدَ فِی الْاَمْرِ.ضِدُّ اَفْرَطَ.کسی معاملہ میں میانہ روی اختیار کی.اَلْقَصْدُ:اِسْتِقَامَۃُالطَّرِیْقِ.راستہ کا سیدھا ہونا.
Page 28
نَقِیْضُ الْاِفْرَاطِ.میانہ روی.وَعَلَی اللّٰہِ قَصْدُ السَّبِیْلِ اَیْ بَیَانُ الطَّرِیْقِ الْمُسْتَقِیْمِ الْمُوْصِلِ اِلَی الْحَقِِّّ.اور عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِکے معنے ہیں حق تک پہنچانے والے سیدھے رستے کا بیان کرنا اللہ کے ذمہ ہے.(اقرب) جَائِرٌ.جَائِرٌ جَارَ (یَجُوْرُ جَوْرًا)سے اسم فاعل ہے اوراَلْجَائِرُ کے معنے ہیں.اَلْحَائِدُ عَنِ الْقَصَدِ راستہ کی سیدھ سے ایک طرف ہونے والا.الزَّائغُ عَنِ الطَّرِیْقِ.کج رَو.اَلظَّالِمُ.ظالم.(اقرب) تفسیر.وَ عَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ کے معنے ہیں.خدا تعالیٰ پر سیدھے راستے کابتاناواجب ہے.یعنی حقٌّ علی اللہ ِ بَیَانُ قَصدِ السَّبِیْلِ.یہی مضمون دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان ہواہے اِنَّ عَلَیْنَا لَلْھُدٰی ( اللّیل:۱۳) یعنی ہدایت کابیان کرنا ہماراہی کام ہے.اورہم ہی پرواجب ہے.قَصْدُ السَّبِیْلِ سے بتایاکہ سیدھا راستہ یا افراط و تفریط سے محفوظ راستہ اللہ تعالیٰ ہی بتاسکتا ہے.ورنہ انسان جب بھی دنیا کے لئے کو ئی راستہ تجویز کرتاہے اس میں افراط و تفریط سے کام لیتا ہے.اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں (سوائے اس کے جو خدا تعالیٰ کی نگرانی میں ہو)جو جنبہ دار نہ ہو.کسی سے اُسے عداوت ہوتی ہے کسی سے محبت.کسی کو اپناسمجھتا ہے اور کسی کوغیر.اس لئے انسانی قوانین میں ہمیشہ یہ نقص ہوتا ہے کہ بعض کے حقو ق تلف کئے جاتے ہیں اوربعض کو زیادہ دیاجاتاہے.پس وہ قانون جس میں سب کے حقوق کاخیال رکھا جائے.نہ کسی کے حق میں کمی کی جائے.نہ کسی کا حق لے کر دوسرے کو دیا جائے صرف اللہ تعالیٰ بناسکتا ہے.جو مخلوق کی مدد کا محتا ج نہیں.اورسب ہی اس کے بندے ہیں.یہ کیسی زبردست سچائی ہے.ہزاروں سالوں سے انسان قانون بنارہاہے.مگر کس طرح اس میں کسی کی حق تلفی کی جاتی ہے اور کسی کو حق سے زیاد ہ دیاجاتاہے.آج کل کے سیاسی اختلافات کو ہی دیکھو.کوئی حکومت مزدوروں کے حق کو دبارہی ہے توکوئی انہی کو سب کچھ دے کر دوسروں کو حقوق انسانیت سے ہی محروم کررہی ہے.اسی طرح انسان چونکہ جذبات کاغلام ہوتاہے.جوقانون بناتا ہے وہ اپنے جذبات کو نمایا ں کردیتاہے.ساری دنیا کے جذبات کاخیال نہ رکھتا ہے نہ رکھ سکتا ہے.اگر رہبانیت کی طرف میلان رکھنے والا دنیا ترک کردینے کا نام ہی نیکی رکھتاہے تودنیا کاحریص دنیوی ترقیات کا نام ہی نیکی رکھتاہے.اس نقص سے وہی تعلیم پاک ہوسکتی ہے جوانسان کے پیداکرنے والے کی طرف سے ہو.جو سب انسانوں کے جذبات سے واقف ہو اورسب کے جذبات کو مناسب حد تک ابھارنے کا خیال رکھے.
Page 29
روحانی کلام میں چھ باتوں کا پایا جانا اس اسلوب بیان سے ظاہر ہے کہ ہرروحانی کلام میں بھی ان چھ باتوں کاپایاجاناضروری ہے.(۱)سردی گرمی کے اثرات سے بچاوے.یعنی افراط و تفریط سے محفوظ رکھے.محبت الٰہی کی کمی کانام سردی ہے اورمذہب کے معاملہ میں غلو سے کام لیتے ہوئے لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا اورانہیں مجبو رکر نا کہ وہ اس مذہب کو قبول کر یں گر می ہے.کلام الٰہی کاکام یہ ہے کہ ایک طرف محبت الٰہی پیداکرے اوردوسر ی طرف اپنے پیروئوں کو میانہ روی سے زندگی بسر کرنے کی تلقین کرے.(۲)وہ غذاکاکام دے.یعنی وہ روحانی طاقتوں کاضروری مجموعہ ہو.اس میں وہ باتیں بتائی گئی ہوں جس سے بد ی کی رغبت سرد پڑتی ہو.اورایسے عقائد کی تلقین کی گئی ہو جن سے اصلاح ہو کر روحانی طاقت وقوت پیداہو.(۳)وہ جمال کاموجب ہو.یعنی جو لوگ اس تعلیم پر عمل کریںوہ خوبصورت نظر آئیں.یعنی اچھے معلوم ہوں.دنیا ان کو دیکھ کرمحسوس کرنے لگ جائے کہ اس کلام نے ان لوگوں کے اندر تبدیلی پیداکردی ہے.(۴)وہ سواری کاکام دے.یعنی انسان کی ذات کو عرفان الٰہی کے ذریعہ سے جلدسے جلد خدا تعالیٰ تک پہنچا دے.اورایک روحانی سفر کو غیر معمولی طوالت سے بچائے.(۵)وہ انسان کے بوجھو ں کواٹھانے والاہو.یعنی انسان کو اس کی ذمہ داریو ںکااحساس کرائے اوراسے رسوم و عادات کی تکلیف دہ زنجیروں سے آزاد کرکے حریت سے کام کرنے کے قابل بنائے.(۶)طاقت و قوت دینے والاہو.یعنی اس پر عمل کرنے سے دین اوردنیا میں عزت حاصل ہو.قوم کانظام مضبوط ہو اوروہ دنیا میں باوقار زندگی بسرکرنے والی ہو.اورآخرت میں عزت پائے جس کلام میںیہ چھ باتیں نہ ہوں وہ کلام الٰہی کہلانے کامستحق نہیں.مِنْهَا جَآىِٕرٌکا مطلب وَ مِنْهَا جَآىِٕرٌ.لوگ کہہ سکتے تھے کہ انسان کے خداتک پہنچنے میں الہام الٰہی کی کیا ضرورت تھی.انسان خود ہی پہنچ جاتا اورخود ہی راستہ تلاش کرلیتا.اس کے جواب میں فرمایاکہ وَ مِنْهَا جَآىِٕرٌ.خود تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ بعض راستے غلط ہوتے ہیں.اگر اللہ تعالیٰ سیدھاراستہ نہ بتائے توبہت سے انسان غلط راستوں پرچل پڑیں گے اورتباہ ہوجائیں گے.یہ عجیب بات ہے کہ ہرانسان تسلیم کرتاہے کہ بعض طوراورطریق ناپسندیدہ ہوتے ہیں اورباوجود اس کے بعض لو گ انہیں اختیار کرلیتے ہیں مگر باوجود اس اقرار کے بعض لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے.
Page 30
مِنْهَاکی ضمیرالسَّبِيْلِ کی طرف جاتی ہے.سبیل مذکر اور مونث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے مِنْهَاکی ضمیرالسَّبِيْلِ کی طرف جاتی ہے.کیونکہ وہ مذکر اورمؤنث دونوں طرح استعمال ہوتاہے.مذکرکی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَاِنْ یَّرَوْاسَبِیْلَ الرُّشْدِ لَایَتَّخِذُوْہُ سَبِیْلًا.وَاِنْ یَّرَوْاسَبِیْلَ الْغَیِّ یَتَّخِذُوْہُ سَبِیْلًا (الاعراف:۱۴۷) اورمؤنث کی مثا ل یہ آیت ہے قُلْ ھٰذِہٖ سَبِیْلِٓیْ اَدْعُوْٓااِلَی اللّٰہِ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ(یوسف :۱۰۹) تاج العروس میں بعض ادباء کاقول ہےکہ سبیل مذکر ہی ہے.اس کی طرف مؤنث کی ضمیر بالمعنیٰ پھر ائی جاتی ہے.اورسبیل کے معنے مُـحَــجَّۃٌ کے لئے جاتے ہیں.مگر یہ امتیاز صرف علمی ہے.اصل مضمون پر اثر انداز نہیں ہوتا.ضمیر کو السَّبِيْلِ کی طرف راجع کرنے میں ایک نکتہ یہاں ضمیر کوالسَّبِيْلِ کی طرف راجع کرکے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے اوروہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعہ سے قَصْدُالسَّبِیْلِ(صراط مستقیم)بتاتا ہے.پھر اس سیدھے راستے سے بگڑ کر ٹیڑھے راستے نکل آتے ہیں.پس ایک الہام کے نزول کےبعد دوسرے الہام کے نزول کی ضرورت باقی رہتی ہے اورکوئی نہیں کہہ سکتاکہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کے نازل کرنے کی کیاضرورت ہے.کیونکہ جب لوگ قَصْدُالسَّبِیْلِ کو کاٹ کر اس میں سے جَآىِٕرٌ راستے نکال لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ پھر ایک اورنبی کی معرفت سیدھا راستہ لوگوںکو بتادے.صرف ضمیر کے مرجع سے ا س وسیع مضمون کی طرف توجہ دلادی گئی ہے کہ سچے دین آخربگڑ کر گمراہی کاموجب ہوجاتے ہیں اوریہ کہ جَآىِٕرٌ راستے بھی قَصْدُالسَّبِیْلِ کے بگڑنے سے پیدا ہوتے ہیں.پس کسی مذہب کاابتدائے نزول میں سچاہونا اُسے ہروقت کے لئے قابل عمل ثابت نہیں کرتا.وَ لَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ.اس میں فرمایا ہے کہ اگراللہ تعالیٰ ہدایت کاکام اپنے ہاتھ میں نہ رکھتاتواس کا ایک ہی منصفانہ طریق ہوسکتا تھا کہ انسانی فطرت کو ایسا بنادیاجاتاکہ وہ غلطی کی طرف جاہی نہ سکتی.مگراس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ یہ حکمت کے خلاف تھا اورجب اس نے ایسا نہیں کیااورانسان کو مقدرت دی ہے کہ وہ غلط راستہ بھی اختیار کرسکتاہے یاصحیح راستہ کوغلط بناسکتا ہے.توپھر اس کے سوااورکون سا منصفانہ طریق رہ جاتا ہے کہ و ہ ہدایت نازل کرکے انسان کو گمراہی سے بچنے اور روحانی ترقی کرنے کاموقعہ دیتا رہے.
Page 31
هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّ وہ ،وہ(پاک)ذات ہے جس نے بادلوں سے پانی اتاراہے اسی میں سےتمہارے پینے کا(پانی جمع کیاجاتا)ہے مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ۰۰۱۱ اوراسی سے وہ درخت(تیار) ہوتے ہیں جن میں تم (مویشیوںکو)چراتے ہو حلّ لُغَات.السَّمَاء السَّمَاءُ کے معنے ہیں آسمان.کُلُّ مَاعَلَاکَ فَاَظَلَّکَ.ہراوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز.سَقْفُ کُلِّ شَیْءٍ وَکُلِّ بَیْتٍ.چھت.رُوَاقُ الْبَیْتِ.برآمدہ.ظَھْرُالْفَرَسِ.گھوڑے کی پیٹھ.السَّحَابُ.بادل.اَلْمَطَرُ.بارش.اَلْمَطَرَۃُ الْجَیِّدَۃُ ایک دفعہ کی برسی ہوئی عمد ہ بارش.اَلْعُشْبُ.سبزہ وگیاہ.(اقرب) تُسِیْمُونَ:تُسِیْمُوْنَ اَسَامَ(جس کامجرد سَامَ ہے)سے مضارع جمع مخاطب کاصیغہ ہے اوراَسَامَ الْاِبِلَ اِسَامَۃً کے معنے ہیں.اَرْعَاھَا.اونٹوں کوچرایا.وَقِیْلَ اَخْرَجَھَا اِلَی الْمَرْعٰی.اوربعض نے اَسَامَ الْاِبِلَ کے معنے یہ کئے ہیں کہ اونٹوں کو چراگا ہ کی طر ف نکالا(اقرب)وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ اسی پانی سے و ہ درخت تیار ہوتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو.تفسیر.السَّمَآءِ کے معنے بادل سماء کے معنے جیساکہ حل لغات میں بتایاگیاہے.بادل کے بھی ہوتے ہیں اوراس جگہ جیساکہ الفاظ سے ظاہر ہے.بادل کے معنے ہی ہیں.فرماتا ہےو ہ بادل جن سے تم کوپینے کا پانی ملتاہے اورجن کے ذریعہ سے وہ درخت اورپودے اُگتے ہیں جن سے تمہارے گلّوںکو چار ہ ملتاہے خدا تعالیٰ نے ہی تواتاراہے.عرب میں پانی کی قلت قرآن کریم کے پہلے مخاطب عرب تھے.جن کے ملک میں کنویں کم ہیں.زیادہ حصہ ملک کاباولیوں سے پانی پیتا ہے.جن میں بارش کاپانی جمع ہو جاتا ہے.اگر وہ پانی جمع نہ کیا جائے.تووہ پیاسے مر جائیں.مکہ مکرمہ میں بھی صرف ایک چشمہ زمزم کا ہے جس کاپانی سخت کھاراہوتا ہے.اورنہر زبید ہ کے نکلنے سے پہلے وہاں پینے کاپانی باؤلیوں سے ہی مہیا ہوتاتھا.بلکہ اب تک بھی نہر زبید ہ کے نکلنے کے باوجود پانی کاکچھ حصہ باولیوںسے ہی مہیاکیا جاتا ہے.جوپیپوں میں ڈال کر لوگ فروخت کرنے کے لئے مکہ میں لاتے رہتے ہیں.باقی
Page 32
ملک کااکثر حصہ بھی ایسے ہی پانیوں پر گذارہ کرتا ہے.اور چونکہ عرب کا اکثر حصہ اونٹوں اوربکریوں بھیڑوں کے گلّوں پر گذارہ کرتاہے ا ن کا چارہ یعنی درخت بھی اسی پانی سے پلتے ہیں.ظاہری سہولتوں کے پیدا کرنے سے روحانی سہولتوں کی طرف اشارہ ا س آیت میں بھی اسی پہلے مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کی سہولت کے لئے قانون قدرت میں ہزاروں اشیاء پیداکی ہیں جن سے تم فائد ہ اٹھاتے ہو.پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہاری روحانی آسائش کاسامان بھی وہ ضرور کرےگا.اورجب کہ دنیوی سامانوں کو تم شوق سے قبول کرتے ہو.کیوں اس کے بنائے ہوئے روحانی سامانوںکو قبول نہیں کرتے.اورجب کہ تم یہ مانتے ہوکہ خدا تعالیٰ کا تمہاری جسمانی ضرورتوں کو پوراکرنا اس کی شان کے خلاف نہیں.تویہ کیوں سمجھتے ہوکہ خدا تعالیٰ کاروحانی سامان پیداکرنا اس کی شان کے خلا ف ہے.اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے والے کا حق نہیں کہ وہ نبیوں کا انکار کرے حق یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود کاہی انکار کرتاہو اورمادی سامانوں کو آ پ ہی آپ سمجھتاہو.وہ تویہ کہہ بھی سکتا ہے کہ نہ کوئی خداہے نہ و ہ کوئی سامان پیداکرتا ہے.لیکن جو خدا تعالیٰ کے وجود کومانتا ہو اوریہ سمجھتاہوکہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے سامانوں کو پیدا کیاہے اسے تو اس بات کے کہنے کاہرگز کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیاپڑی ہے یااسے کیا حق ہے کہ انسانوںکی ہدایت کے لئے نبی بھیجے اورکتابیں اتارے.کیونکہ اس کا ایک عقیدہ دوسرے عقیدہ کو ردّ کرتاہے.اوراسے اپنی غلطی معلوم کرنے کے لئے کسی اوردلیل کی ضرورت نہیں.قانون قدرت سے پیدا شدہ سب سامان انسان ہی کے کام آتے ہیں اس آیت میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ قانون قدرت جس قدر ساما ن پیداکرتاہے وہ حقیقتاً انسا ن ہی کے کام آتے ہیں.پانی بھی اترتا ہے تو اس کے لئے.کیونکہ جانور اوردرخت اگراس سے پلتے ہیں توان کو بھی توانسان ہی استعمال کرتاہے.پس آخری نقطہ کائنات کاانسان ہی ہے.اوراس کی روحانی ترقی کے سامان پیداکرنا خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں.بلکہ پیدانہ کرنااس کی شان کے خلاف ہے کہ ایک ایسی مخلوق پیداکی جس کے فائدہ کے لئے ایک حیرت انگیز وسیع نظام بنایا.لیکن اس کی پیدائش کاکوئی اعلیٰ مقصد نہ قراردیا.پہلی آیات میں حیوانات کی پیدائش کا ذکر تھااورحیوانی غذاکا.اس آیت میں پانی کا ذکر کیا اورنباتی غذا کا.اسی مضمون کو اگلی آیت میں اوروسیع کیاگیا ہے.
Page 33
يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ النَّخِيْلَ وَ الْاَعْنَابَ وہ اس کے ذریعہ سے تمہارے لئے کھیتی اورزیتون اورکھجور کے درخت اورانگور اور(دوسرے )ہرقسم کے پھل وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۠۰۰۱۲ (بھی )پیداکرتاہے.ان لوگوں کے لئے جوفکر سے کام لیتے ہیں اس میں یقیناًایک نشان (پایاجاتا)ہے.تفسیر.پہلی آیت میں پانی کا ذکر کیاگیاتھا جسے انسان پیتے ہیں.اورایسے درختوں کی پیدائش کا ذکر کیاتھا جن سے جانو رپلتے ہیں.اورپھر ان جانوروں سے انسان فائدہ اٹھاتاہے.اب ایسی نباتی غذائوں کا ذکر فرماتا ہے جن کو براہ راست انسان استعمال کرتاہے.اورفرماتا ہے اس پانی سے کچھ اورنباتات بھی اُگتی ہیں جن کو انسان براہ راست استعمال کرتا ہے.ان میں سے کچھ تو کھیتیاں ہیں جن سے انسانی غذاکے لئے غلّہ پیدا ہوتاہے.کچھ درخت ہیں جن سے انسان کے کھانے کے لئے پھل اترتا ہے.جیسے زیتون اورکھجور اورانگور اوران کے علاوہ اوربھی کئی اقسام کے میوے اورپھل.پھرکیا تم اس امر پر غور نہیں کرتے کہ جس طرح انسان کے سوادوسرے حیوانات انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں.اسی طرح نباتات بھی اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں.جس طرح زمین اگانے کے لئے پانی کی محتاج ہے اسی طرح عقل جوہر دکھانے کے لئے پانی کی محتاج ہے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایاکہ زمین میںاُگانے کی خواہ کس قدر بھی طاقت ہو وہ آسمانی پانی کے بغیر کچھ نہیں اُگاسکتی.اسی طرح انسانی فطرت کاحال ہے کہ انسانی ذہن اورانسانی عقل خواہ کس قدر اعلیٰ ہو وہ اپنے جوہر دکھانے کے لئے آسمانی پانی کی محتاج ہے.اوراس پانی کے بغیر انسانی عقل کی تکمیل نہیں ہوتی.پس صرف اپنی عقل پر اپنی روحانی ترقیات کا انحصار رکھنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ شخص جو بغیر پانی کے کھیتی اُگانے کی کوشش کرے.بے شک کھیتی بعض دفعہ اُگ توآئے گی مگر وہ اپنی پوری شان ظاہر نہیں کرے گی.الہام کے بغیر فطرت کو نشوونما نہیں ہوتا بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ نبی کون سی نئی چیز دنیامیں لاتے ہیں.سب باتیں جو وہ کہتے ہیں پہلے سے ہی انسانی فطرت میں موجود ہیں.ان کا بھی ا س آیت میں جواب دیاگیا ہے اورپانی کی مثال سے بتا یاہے کہ کسی چیز کاموجود ہونا اوربات ہے اوراس کا نشوونماپانااوربات ہے.گوسب کچھ جو نبی بتاتے ہیںفطرت کے مطابق ہوتاہے.لیکن الہام کے بغیر فطرت کو نشوونمانہیں حاصل ہوتا.جس طر ح پانی
Page 34
کے بغیر زمینی طاقتیں اُبھرتی نہیں.کوئی نہیں کہتا کہ جب بیج اورنشوونما کی طاقت زمین میں موجود ہے توپانی کی کیاضرورت ہے.پانی نہ بیج لاتا ہے اور نہ زمین میں نشوونما کی طاقت پیداکرتا ہے.مگرہر اک جانتا ہے کہ پانی بیج اورنشوونما کی طاقت لاتاتونہیں.پروہ نشوونما کی طاقت کو اُبھارتا ضرورہے.اوراس کے بغیر و ہ طاقت بالفعل اپنا اظہار یاکرتی ہی نہیں یابہت کم کرتی ہے.یہی حال الہام کاہے کہ وہ نئی فطرت نہیں بناتا.لیکن فطرت کی خوابیدہ طاقتوںکو اُبھارتا ہے.نباتات کا ذکر ان کے فوائد کے لحاظ سے کیا گیا ہے جس طرح حیوانی فوائد کے بیان میں ترتیب کو مدنظر رکھا گیا تھا کہ پہلے حیوانی غذاکا ذکر کیا تھا جوانسان کے لئے نہایت ضروری ہے اورپھر حیوانات کے دوسرے فوائدبیان کئے تھے.جوگوویسے ضروری نہیں لیکن انسانی شان کے بڑھانے والے ہیں.نباتات کے ذکر میں بھی پہلے کھیتی کا ذکر کیا ہے جوعام انسانی غذا پیداکرتی ہے.پھر زیتون کا جو روٹی کے ساتھ سالن کاکام دیتا ہے اورپھر کھجور کا جو غذابھی ہے اورمیوہ بھی.اورپھر انگور اور دوسرے پھلو ںکا جوضروری غذاتونہیں.لیکن انسانی صحت اوردماغی طاقتوں کے بڑھانے کاموجب ہوتے ہیں.غذا کے حیوانی ہونے کے متعلق ایک اعتراض اور اس کا جواب شاید کوئی اعتراض کرے کہ انسان کی مقدم غذاحیوانی نہیں کیونکہ ایک خاصہ طبقہ دنیا کا صرف نباتی غذااستعمال کرتا ہے مگر یہ اعتراض قلّتِ تدبر کانتیجہ ہوگا.کیونکہ جو حیوانی غذااستعمال نہ کرنے کادعویٰ کرتے ہیں وہ بے شک گوشت تو نہیں کھاتے.مگر ان کی اہم غذا بھی حیوانی ہوتی ہے.ماں کادودھ پئے بغیر کتنے بچے پلتے ہیں.پھر کیا ماں کادودھ حیوانی غذانہیں؟ اورجو ماں کادودھ نہیں پیتےوہ جانوروں کادودھ پیتے ہیں اوروہ بھی حیوانی غذا ہے.اورجو لوگ حیوانی غذاکے استعمال سے بظاہر انکار کرتے ہیں وہ بڑی عمرمیں بھی گھی دودھ استعمال کرتے ہیں جو حیوانی غذائیں ہیں.پس ایسا آدمی کوئی بھی نہیں جس کی اہم ترین غذا حیوانی نہ ہو اورجو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حیوانی غذااستعمال نہیں کرتے.وہ یاتوخود فریب میں مبتلاہوتے ہیں یاجان بوجھ کر دوسروں کو فریب دیتے ہیں.وہ یہ توکہہ سکتے ہیں کہ ہم گوشت نہیں کھاتے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی حیوانی غذابھی استعمال نہیں کرتے.اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۠.غذائوں کے ذکر کے آخر میں فرمایاکہ اس میں فکر کرنے والوں اورسوچنے والوں کے لئے نشان ہے.اس سے ایک تواس طرف اشار ہ کیاکہ انسانی دماغ غذاسے نشوونماپاتاہے.اسی طرح روحانیات سے تعلق رکھنے والا دماغ روحانی غذائوں سے نشوونماپاتاہے.دوسرے اس طرف اشارہ کیا کہ فطرۃ کے
Page 35
اندرافکار تو موجود ہوتے ہیں.مگران کے ابھارنے کے لئے عمدہ غذاکی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روحانی افکار بھی انسان کے اندرموجود توہوتے ہیں مگر ان کے ابھارنے کے لئے بھی روحانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے.سب انسان ایک ہی قسم کے ہیں.مگر ایک اعلیٰ درجہ کی قوت فکریہ رکھتا ہے دوسرانہیں.اوراس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک کومناسب غذا ملتی ہے دوسرے کونہیں.یہی حال روحانی عالم کا ہے.سب ہی انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ ہے لیکن ایک آدمی جوروحانی غذائیں کھاتا ہے.اس کی قوت فکریہ کو جِلا اورروشنی مل جاتی ہے دوسرے کو نہیں.وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ١ۙ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ١ؕ اوراس نے رات اوردن کو اورسورج اورچاندکو تمہارے لئے بے اُجرت خدمت پر لگارکھا ہے وَ النُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ اور(دوسرے )تمام (سیارے اور)ستارے (بھی )اس کے حکم سے بلااجرت (تمہاری)خدمت پر متعین ہیں يَّعْقِلُوْنَۙ۰۰۱۳ جولوگ عقل سے کام لیتے ہیںان کےلئے اس میں یقینا کئی نشان (پائے جاتے )ہیں.حلّ لُغَات.سَـخَّرَ سَـخَّرَکے لئے دیکھو سورۃ رعد آیت نمبر ۳.سَـخَّرَہٗ.کَلَّفَہٗ عَمَلًا بِلَا اُجْرَۃٍ.سَـخَّرَہُ کے معنے ہیں کہ اس کو بغیر اجرت یا بدلہ کے کسی کام پر لگادیا.ذلَّلَہُ اس کو مطیع کردیا.وَکُلُّ مَقْھُوْرٍ لَایَمْلِکُ لِنَفْسِہِ مَایُخَلِّصُہٗ مِن الْقَھْرِ فَذٰلِکَ مُسَخَّرٌ.اور ہر وہ شخص جو کسی کے قبضہ میں ہو اور آزاد رہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے مسخر کہتے ہیں.(اقرب) یَعْقِلُوْنَ.یَعْقِلُوْنَ عَقَلَ(یَعْقِلُ عَقْلًا)سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اورعَقَلَ الْغُلَامُ کے معنے ہیں.اَدْرَکَ.لڑکابالغ ہوگیا.عَقَلَ الشَّیْءَ عَقْلًاکے معنے ہیں.فَھِمَہُ وَ تَدَبَّرہُ کسی چیز کو سمجھااوراس پرغور کیا.عَقَلَ الْبَعِیْرَ :ثَنیٰ وَظِیْفَہُ مَعَ ذِرَاعِہٖ فَشَدَّھُمَا مَعًا بِحَبْلٍ.اونٹ کی پنڈلی کو اس کی ران کے ساتھ ملا کر باندھ دیا.اورعِقَالٌ اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کی پنڈلی باندھی جاتی ہے.(اقرب) پساِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَکے معنے ہوں گے کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں یعنی بات کو سمجھتے اوراس پر تدبر
Page 36
کرتے ہیں.ان کے لئے اس میں کئی نشان پائے جاتے ہیں.تفسیر.جمادات سے تعلق رکھنے والی نعمتوں کا ذکر اب ایک اورقسم کی نعمتوں کا ذکر کیا جو جمادات سے تعلق رکھتی ہیں.اوران میں سے بھی انہی کا انتخاب کیاہے جو انسانی دماغ کے نشوونما پر خاص طورپر اثر انداز ہوتی ہیں.بے شک انسان لوہے.لکڑی.سونے.چاندی.پیتل سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ان اشیاء سے وہ بڑافائدہ بیرونی آرام کی قسم کا حاصل کرتا ہے.برتن بناتا ہے.مکان بناتا ہے.آلات بناتا ہے.براہ راست ان اشیا ء کااثر انسانی دماغ پر نہیں پڑتا.لیکن چونکہ اس جگہ انسانی دماغ کے نشوونما کے ذکر پر زوردینا مقصود ہے.ا س لئے جمادات کی مذکورہ بالا اقسام کی بجائے رات اوردن ،سورج ،چاند اورستاروں کا ذکر کیاگیا.رات اور دن درحقیقت جمادی اثرات میں ہی شامل ہونے کے مستحق ہیں کہا جاسکتا ہے کہ رات اوردن تو جمادات میں سے نہیں.اوریہ درست بھی ہے.لیکن اس سے کسی کو انکار نہیں ہوسکتاکہ رات اورد ن کے فوائد سورج اورچاند اورستاروں کے اثرات سے وابستہ ہیں.اور وہ اجرام فلکی ان کے ذریعہ سے اپنی تاثیرات ظاہر کرتے ہیں.یعنی اپنی شعاعوںکو نازل کرکے یاان کو روک کر.اس لئے رات اوردن بھی درحقیقت جمادی اثرات میں ہی شامل ہونے کے مستحق ہیں.رات اور دن کے علاوہ سورج چاند وغیرہ کے نام کی ضرورت اگر کہا جا ئے کہ رات اوردن جب سورج اورچاند اورستاروں کے ظہور اورفوائدپر دلالت کرتے ہیں.توپھر سورج چاند وغیرہ کا الگ نام لینے کی کیا ضرورت تھی تواس کا جواب یہ ہے کہ گورات اوردن ان اجرام فلکی کی تاثیرات کے ظہور کا نام ہیں.لیکن ان کے علاوہ بھی سورج اورچاند اورستاروں کے اثرات ہیں اور ان سے ایسی تاثیرات بھی دنیا پر پڑتی ہیں جو آنکھوں سے نظر آنے والی شعاعوں کے علاوہ دوسرے ذرائع سے انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں.جیسے برقی یامقناطیسی اثرات.اوران کے سوااور کئی قسم کی تاثیرات ہیں.جوسائنس روز بروز دریافت کررہی ہے.اور کئی وہ شائد کبھی بھی دریافت نہ کرسکے.(The Heavens vol:1 page: 82) پس باوجود اس کے کہ رات اور دن اجرام فلکی کے تاثیرات کے ظہور کاذریعہ ہیں.ان کے علاوہ بھی سورج اورچاند ستاروں کا نام لینے کی ضرورت تھی.تاان دوسری تاثیرات کا ذکر کیا جائے جن سے انسانی دماغ فائدہ اٹھارہا ہے.اس جگہ یہ سوال ہو سکتاہے کہ اگر یہ بات ہے.توپھر رات اوردن کے ذکر کی ضرورت نہ تھی.سورج چاند اورستاروں کا ذکر کافی تھا.اس کا جواب یہ ہے کہ سورج چاند اورستاروں کی دوسری تاثیرات سے تو عرب کے لو گ
Page 37
ابھی واقف نہ تھے.صرف رات اوردن کی تاثیرات سے ان کو آگاہی تھی.اوراب بھی علمی طبقہ کے علاوہ باقی لوگ رات اوردن کی تاثیرات اوران کے فوائدسے توآگاہ ہیں.لیکن سورج چاند اورستاروں کی دوسر ی تاثیرات سے واقف نہیں ہیں.پس فائدہ کو وسیع کرنے کے لئے اورقرآن کریم کے پہلے مخاطبوں کے ذہنوں سے مضمون کو قریب الفہم بنانے کے لئے ضروری تھا کہ دن اوررات کو الگ بھی بیان کردیاجاتا تاکہ ان کادماغ بسہولت آیت کے مضمون کی طرف منتقل ہوسکتا.شعاعوں کی تاثیر کے متعلق سائنس کی تحقیقات یاد رہے کہ سائنس کی موجود ہ تحقیق نے سپکٹرم کے ذریعہ سے جوایک ایساآلہ ہے جس کے ذریعہ سے روشنی کی شعاعوں کو پھا ڑ کر الگ الگ کرلیا جا تاہے(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظSPECTROSCOPY).یہ معلومات حاصل کی ہیں کہ فلاں ستارے میں فلاں قسم کی دھاتیں ہیں اورفلاں میں فلاں قسم کی.جس سے معلوم ہوتاہے کہ صرف روشنی ہی نہیں بلکہ روشنی کے ساتھ مختلف دھاتوں کی تاثیرات بھی دنیا پر اُترتی رہتی ہیں اور ان سے اہل دنیا کے دماغ اورقویٰ پر مختلف اثرات نازل ہوتے رہتے ہیں.چاند کی شعاعوں کی تاثیر چاند کی شعاعوں کی تاثیرات توکئی رنگ میں دنیا پر ظاہرہوتی رہتی ہیں.چاند گرہن کا اثر عام طور پر ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ چاند گرہن جب مکمل ہو توحاملہ عورتوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے.چنانچہ ایسے وقت میں حاملہ عورتیں کمروں سے باہر نہیں نکلتیں.گوعام طور پر اسے وہم سمجھا جاتا ہے مگر میں نے اس سوال پر خاص طورپر غور کیا ہے اورمعلوم کیا ہے کہ جب چاند گرہن مکمل ہو تواس کے بعد بہت سی عورتوں کی زچگی سخت تکلیف دہ ہوتی ہے.اوران میں بکثرت موتیں ہوتی ہیں.میں نہیں کہہ سکتا کہ تکلیف اٹھانے والی عورتیں وہ ہوتی ہیںجو ایسے وقت میں چاند کودیکھتی ہیں.یااس کے بغیر بھی ان پر یہ تاثیر عمل کرتی ہے.مگر بہرحال میں نے کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہے اوردوسروں کو بھی بتایا ہے.جنہوں نے اپنے تجربہ سے اس کی تصدیق کی ہے.یہ بھی نہیں کہاجاسکتا کہ یہ تاثیر ہمیشہ ہوتی ہے یااس کاظہور بعض اور ستاروں کی نسبت سے ہوتاہے.یعنی چاند دوسرے ستارو ںسے ایک خاص زاویہ پرہوتواس وقت اس کی یہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے یاآزادانہ ہوتی ہے.یہ منجم ہی بتاسکتے ہیں.میں نے تو بعض توہمات کی تحقیق کرتے ہوئے جوچاند گرہن کی حاملہ عورتوں پر تاثیر کے متعلق ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں یہ امور مشاہد ہ کئے ہیں.ان کو معیّن اورعلمی صورت دینا ستاروں کے علماء کاکام ہے.جمادات کی روشنیاں، شعاعیں، مقناطیسی تاثیرات انسانی نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں خلاصہ یہ کہ جمادات کی روشنیاں اورشعاعیں اورمقناطیسی تاثیرات بھی انسانی نشوونما پر خاص اثر ڈالتی ہیں جن میں سے
Page 38
بعض ظاہرہوتے ہیں بعض مخفی.اور بعض بلا واسطہ ہوتے ہیں اوربعض بالواسطہ.بالواسطہ سے میری مراد اُن تاثیرات سے ہے جو نباتا ت یا حیوانات پروارد ہوتی ہیں.اورپھر ان حیوانات اور نباتات کو انسان استعمال کرتاہے.سورج اور چاند کی روشنی کی تاثیر سورج اورچاند کی موٹی تاثیرات سے مراد و ہ تاثیرات ہیں جوصحت پر پڑتی ہیں.دن کی روشنی کئی قسم کی بیماریوں کو دور کرتی ہے اورانسانی جسم میں صحت کاماد ہ بڑھاتی ہے.چنانچہ جولوگ دن رات بند کمروں میں رہتے ہیں ان کی صحت خراب ہوجاتی ہے.(The Vitamins by H.C Sherman and S.L Smith 2nd edition 1931.p.296,298) اسی طرح رات کی تاریکی اعصاب پر تسکین دہ اثر ڈا لتی ہے.اسی وجہ سے رات کی نیند بہت آرام دہ ہوتی ہے بہ نسبت دن کی نیند کے.خصوصاً دوپہر کی نیند کے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ آرام کم ملتا ہے بلکہ بعض دفعہ اس سے نزلہ وغیرہ کی قسم کی بیماریاں بھی پیداہوتی ہیں.غرض دن کام کے لحاظ سے زیاد ہ بہتر ہے اوررات آرام کے لحاظ سے پھر بعض قسم کی سبزیوں پر دن کی روشنی کی مبارک تاثیر پڑتی ہے اوربعض پر رات کی روشنی کی جوچاند اورستاروں سے آتی ہے.چنانچہ ککڑی رات کواس سرعت سے بڑھتی ہے کہ دیکھ کر حیر ت آتی ہے.بعض دفعہ کھیت کے پاس بیٹھو تویوں آواز پیداہوتی ہے گویا کہ ککڑی پتوں میں پھیل رہی ہے.اسی طرح بعض پھول چاندنی راتوں میں کھلتے ہیں بعض اندھیر ی راتوں میں.اوریہ سب امور اس امر کی شہادت ہیں کہ رات اوردن اوراجرام فلکی کی تاثیرات اہل دنیاکے نشوونما پر خاص اثر ڈال رہے ہیں.اوران کاوجود صرف آنکھو ں کے لئے روشنی مہیا کرنا نہیں.یااعصاب کے آرام کے لئے تاریکی دینا ہی نہیں.بلکہ ان کے علاوہ بھی ان کی وسیع تاثیرات ہیں.جن لوگوں کو چاند کی روشنی میں سیر کرنے کاموقع ملا ہے.انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس وقت خیالات میں ایک عجیب قسم کا ہیجان پیداہوجاتا ہے اورقوتِ فکریہ میں ایک تلاطم پیداہوجاتا ہے.اسی طرح رات اوردن اورسور ج اور چاند اور ستاروں کاتعلق راستہ دکھانے سے بھی ہے.دن کوسورج کی روشنی اگر سب فضاکو روشن کرکے راستہ دکھانے میں ممدہوتی ہے اورجہات اربعہ یعنی مشرق مغرب شمال جنوب کوبتا کر اگر راہگیروں کی راہنمائی کرتی ہے.تورات کو چاند اپنی روشنی سے سورج کاساکام کرتا ہے اورستارے اپنے مقامات سے ہدایت کاموجب ہوتے ہیں.چنانچہ سمندروں میں جہازوں کے چلنے میں ستاروں کے مقامات خاص طورپر مد د کرتے ہیں.حیوانی اور نباتاتی غذا کے بعد مخفی غذا کی طرف اشارہ خلاصہ یہ کہ رات اوردن اورسورج چاند اورستارے انسانی دماغ کو نشوونمادینے میں اوراس کے کاموں میں سہولت پیداکرنے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں.
Page 39
اوریہ جمادات میں سے ہیں جوانسان سے بہت دور کا تعلق رکھتے ہیں.اوران کی ذاتی نشوونما کی طاقت ایسی مخفی ہے کہ اس کااندازہ ظاہر ی نگاہ سے نہیں کیا جاسکتا.لیکن باوجود اس کے وہ اپنی تاثیرات سے نباتات اورحیوانات کے نشوونما پر ان کے ذریعہ سے بھی اوربراہ راست بھی انسا ن کے نشوونما پر خاص اثر ڈالتے ہیں.پس حیوانی غذا اور نباتی غذا کے بعد اس مخفی غذاکی طرف اشارہ کیا جو انسان جمادات سے اورخصوصاً ان بڑے جمادی اجرام سے جوآسمان پر ہیں حاصل کررہا ہے.حیوانوں اور نباتات کے متعلق پیدا کرنے کے الفاظ اور سورج اور چاند کے لئے سَخَّرَکا لفظ استعمال کرنے کی وجہ اس جگہ ایک اورلطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حیوانوں اورنباتات کے بارہ میں توصرف یہ فرمایاتھا کہ ہم نے ان کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے.لیکن رات اوردن اورسورج ،چاند، ستاروں کے ذکر میں سَـخَّرَ کالفظ فرمایا ہے.جس کے معنے ہیںبغیر اجرت کے کام پر لگارکھا ہے.یہ فرق اس لئے کیا کہ حیوانوں اورنباتا ت سے انسان جو فائدہ اٹھاتاہے.اس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے زور سے یہ فائدہ اٹھایاہے گویہ ہےغلط.کیونکہ خدا تعالیٰ ان کو پیدانہ کرتا تووہ فائدہ کہاں سے اٹھاتا.مگر پھر بھی چونکہ بظاہر اس میں انسانی اختیار کا دخل ہے.وہاں صرف پیدائش کی طر ف اشارہ کیا ہے.مگر اس آیت میں جو فوائد بیان ہوئے ہیں.ان کے حصول میں انسانی تصرف کاکوئی دخل نہیں.اس لئے اس جگہ سَخَّرَ کالفظ استعمال کرکے بتایاکہ کم سے کم ان اشیا ء کی نسبت تو تم کوماننا پڑے گاکہ وہ جو انسانی خد مت کررہی ہیں ان کا موجب حکم الٰہی ہے.کیونکہ ان پر تم کو کوئی تصرف حاصل نہیں ہے.اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ امور عقل مندوں کے لئے نشان ہیں.اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت فکر یہ نزدیک کی اشیاء کاحال معلوم کرتی ہے اورقوت عقل دور کی چیزوں سے بھی تعلق رکھتی ہے.چونکہ پہلی آیات کی اشیاء خوراک سے تعلق رکھتی تھیں اورانسان ان کے اثرکو اپنے اند ر محسوس کرتاہے اس لئے وہاں فکر کا لفظ رکھا ہے.اوران چیز وں کی تاثیر بیرونی ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا دانش سے تعلق رکھتا ہے اس لئے لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ فرمایا.
Page 40
وَ مَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اورجوکچھ اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کیا ہے جس کی مختلف قسمیں ہیں (وہ بھی تمہارے کام آرہا ہے )اس لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ۰۰۱۴ میں (بھی)ان لوگوں کے لئے جونصیحت حاصل کرتے ہیں یقیناًایک نشان (پایاجاتا)ہے.حلّ لُغَات.ذَرَاَ: ذَرَأَ اللّٰہُ الْخَلْقَ کے معنے ہیں خَلَقَہُمْ.اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا.ذَرَأَ الشَیْءَ.کَثَّرَہٗ.کسی چیز کو زیادہ کیا.ذَرَأَالْاَرْضَ:بَذَرَھَا،زمین میں بیج بویا.(اقرب) اَلْوَانٌ:اَلْوَانٌ لَوْنٌ کی جمع ہے.اوراَللَّوْنُ کے معنے ہیں مَافَصَلَ بَیْنَ الشَّیْءِ وَبَیْنَ غَیرِہِ.یعنی لون اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے ایک چیز دوسری چیز سے ممتاز نظرآتی ہے.اَللَّوْنُ:النَّوْعُ.قسم.اَللَّوْنُ: صِفَۃُ الْجَسَدِ وَھَیْئَتُہُ مِنَ الْبَیَاضِ وَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَۃِ.کسی جسم کاسیاہ ،سفید سرخ رنگ.(اقرب) تفسیر.ذَرَاَ کے لفظ سے سب اشیاء کی پیدائش کا ذکر ذَرَاَ کے معنے پیداکرنے کے ہیں.پس اس جگہ ان سب اشیاء کا ذکر ہے جودنیا میں موجود ہیں.خواہ حیوانات کی قسم کی ہوں ،خواہ نباتات کی قسم کی خواہ جمادات کی قسم کی.رنگوں کے اختلاف اور تاثیر کا ذکر ان کی علمی دریافت سے پہلے اس آیت سے ایک نئے مضمون کو شروع کیا اوررنگوں کے اختلاف کو پیش کیا کہ وہ بھی تاثیرات رکھتے ہیں اورانسان ان سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے.قرآن کریم کیساعظیم الشان کلام ہے جوان حکیمانہ امورکو اس زمانہ میں بیان فرماتا ہے جبکہ دنیا ان سے کلی طور پر ناواقف تھی.رنگوں کی تاثیرات کی دریافت علمی طورپر موجودہ زمانہ میں ہوئی ہے.حتی کہ بنفشی شعاعوں اورماوراء بنفشی شعاعوں اور کئی قسم کی دوسری شعاعوں کی دریافت سے بیماریوں کے علاج میں غیر معمولی مد دملی ہے.اورطب میں بھی ایک نیا باب علاج باللَّون کا کھل گیا ہے.یعنی مختلف رنگوں کی بوتلوں میں پانی رکھ کر اورسورج کی شعاعوں کے مقابل پر رکھ کر خالی پانی کو دوا کی صورت میں بد ل دیاجاتا ہے.گویہ طریق علاج اب تک علمی حد تک نہیں پہنچا.مگر اس کے بعض فوائد ناقابل انکارہیں.ایک ہی قسم کی اشیاء کا رنگوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف تاثیرات کا ظاہر کرنا ان کے علاوہ یہ
Page 41
امر تجربہ شدہ ہے کہ ایک ہی قسم کی اشیا ء رنگ کے اختلاف کی وجہ سے مختلف تاثیرات ظاہر کرتی ہیں.مثلاً توت ہے.اس میں سے سفید گلے میں خراش پیداکرتاہے اورسیاہ توت خنا ق جیسی مرض میں مفید ہوتاہے.صندل سفید اورسرخ تاثیرات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بعض امور میں قوی یاضعیف ہو تے ہیں (خزائن الادویہ مصنفہ حکیم محمد نجم الغنی رامپوری مطبوعہ خادم التعلیم برقی پریس پیسہ اخبار لاہور ۱۹۲۶ء جلد ۵ ص ۹۲).یہی حال اَورسینکڑوں اشیاء کا ہے کہ چیز ایک ہی ہوتی ہے.لیکن رنگ کے تغیر سے اس کے فوائد میں تغیر پیداہوجاتا ہے.بہت سی چیزوں کے فوائد معلوم ہوگئے ہیں اوربہت سی کے ابھی مخفی ہیں.مگراس حد تک اس علم کا انکشاف ہوچکا ہے کہ رنگوں کی تاثیرات کا انکار نہیں کیا جاسکتا.طب میں مختلف رنگوں سےبیماریوں کا علاج موجودہ طب میں تو مختلف رنگوں سے بعض شدید بیماریوں کاعلاج کیا جاتا ہے.اگر زرد رنگ کی اکری فلیوین بیرونی زخموں کے لئے مفید ہے تو مرکیوروکروم اندرونی زخموں کے لئے مفید ہے.اسی طرح اور کئی رنگ ہیں.میں نے ایک دفعہ اکری فلیوین کودیکھ کرخیا ل کیا کہ معلوم ہوتا ہے زرد رنگ کی تاثیر زخموں کے لئے اچھی ہوتی ہے.اوراسی وجہ سے پرانے زمانہ میں زخموں کے علاج کے لئے ہلدی کو بکثرت استعمال کیا جاتا تھا.اس خیال سے میںنے ہلدی کارنگ نکال کر زخموں کے لئے ایک ڈاکٹرکودیا.انہوںنے تجربہ کرکے بتایا کہ گواکری فلیوین جیسی تاثیر تونہیں.مگراس کے ساتھ ملتی ہوئی تاثیر آپ کی دوامیں ضرور تھی.اس فرق کی وجہ میں نے یہ سمجھی کہ اس حد تک میںاس کا جوہر نہیں نکال سکاجس حد تک کہ جرمنوں نے نکال لیاہے ورنہ بات وہی ہے.غرض رنگوں کی تاثیرات ایک ثابت شدہ حقیقت ہیں.گواب تک یہ علم مکمل نہیں ہوا.قرآن کریم اس کی طرف اشارہ فرماتا ہے اورتوجہ دلاتا ہے کہ اجرام تو الگ رہے ان کے رنگ تک تمہارے فائدہ میں لگے ہوئے ہیں.اورکیسی کیسی باریک راہوںسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری جسمانی ترقی کے سامان پیداکئے ہیں.مگر تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ روحانی ترقی کے لئے بھی ویسے ہی وسیع بلکہ ان سے بھی زیادہ وسیع سامان پیداکرنے کی ضرورت ہے.رنگوں کے ذریعہ سے ایک ہی جنس کی دو چیزوں میں امتیاز علاوہ ازیں اس رنگو ں کے تغیر سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک ہی چیزکے کئی رنگ ہوتے ہیں.اوراگرایک طرح اسے اپنی قسم کی دوسری چیزوں سے اتحاد ہوتا ہے تودوسری طرح ان سے وہ مختلف بھی ہوتی ہے سب انسان انسان ہیں مگر کوئی دوآدمی ظاہری شکل یاباطنی قوتوں میں یکساں نہیں ملتے.سب اونٹ اونٹ ہیں مگر پھر ہر اونٹ کی شکل اورعقل دوسرے اونٹ سے مختلف ہوتی
Page 42
ہے.گویا ایک طرف شدید اتحاد ہے تودوسری طرف شدید اختلاف.یہی حال نباتات کا ہے سب آموں کے درخت آموں کے ہی درخت ہیں مگر ہردرخت دوسرے سے الگ پہچاناجاتا ہے اورایسا ہی حا ل ان کے پھلوں کاہے.غرض دنیا میں ہرجنس کے افراد دوسرے افراد سے مشابہت رکھتے ہیں مگر پھر ان سے مختلف بھی ہوتے ہیںاگر رنگوں کایہ فرق نہ ہوتا تو ایک کودوسر ے سے پہچاننا ناممکن ہوجاتا.اب تو ہر ماں باپ اپنے بچے کو ہربیٹااپنے ماں باپ کو ہر خاوند بیوی کو بیوی خاوند کو بھائی بھائی کو پہچانتا ہے.اگرامتیازی نشان نہ ہوتے توپہچانناکس قدر مشکل ہوتا ہے.مگراللہ تعالیٰ نے کس قد روسیع فرق ہر شے میں رکھا ہے.سفید رنگ ہے تواس کے اس قدرمدارج ہیں کہ انسان ان کے نام نہیں رکھ سکتا.سیاہ رنگ ہے توا س کے اس قدرمدارج ہیں کہ ان کی گنتی نہیں کی جاسکتی.صرف آنکھ اس فرق کو پہچانتی ہے اورا س فرق کی وجہ سے فوراً دوچیزوں میں امتیاز کرلیتی ہے.مگرزبان اس فرق کو اکثر نہیںبتاسکتی.اللہ تعالیٰ اسی امتیاز کے روحانی پہلو کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو جس طرح اشیاء کے مادی رنگ مختلف ہیں اسی طرح ان کے باطنی رنگ بھی مختلف ہیں.پھر جس طرح انسان کے جسم کی ضروریات مختلف ہیں اس کے مقابل پر مختلف رنگ کی اشیا ء بھی اللہ تعالیٰ نے پیداکی ہیں.نہ انسان کے جسم کی ضرور توںکو کلی طور پر کوئی سمجھ سکتاہے نہ ان کے پوراکرنے کے سامان کوئی پیداکرسکتاہے.کیونکہ ہرانسان کاذوق الگ ہوتا ہے اوراس کے جسم کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں کسی کو میٹھا مفید ہے کسی کو کھٹا.کسی کو کدوپسند ہے کسی کو بینگن.ایک کیلے پر جان دیتا ہے دوسرا اس کے چکھنے کی برداشت نہیں رکھتا.غرض انسانی طبائع ایسے مختلف انواع کی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیاجاسکتا.کیابلحاظ قوت ذائقہ کے اور کیا بلحاظ مختلف تاثیرات سے مناسبت رکھنے کے ان میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے.اورہر اک کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے بیرونی اشیاء میں پوری کرچھوڑی ہے.انسان تو ان اختلافات کی اقسام گن تک نہیں سکتا.وہ ان کے مطالبات کو پوراکرنے کی طاقت کہا ں رکھ سکتا تھا.اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے مختلف رنگوں اورمختلف ذوقوں اورمختلف مزاجوں کے لوگوں کو پیدا کیا.اورپھر ان کی ضرورتوں کوپوراکرنے کے لئے ویسی ہی مختلف الانواع چیزیں بھی پیداکردیں.لون کے معنے مختلف انواع کے ان معنوں کے روسے لون کے معنے نہ صرف رنگ کے لئے جائیں گے بلکہ نوع کے بھی.اورجیساکہ حل لغات میں بتایا گیا ہے.لون کے معنے نوع کے بھی ہوتے ہیں.اس مضمون سے اللہ تعالیٰ نے اس طر ف اشارہ فرمایا ہے کہ دیکھو دنیا میں مختلف رنگوں اورمختلف انواع کی چیزیں اس نے پیداکی ہیں تاکہ تمہاری مختلف ضرورتوں اور تمہارےمختلف میلانوںکوپوراکرے.تم خود یہ کام نہیں
Page 43
کرسکتے.پھر تم کس طرح سمجھ سکتے ہوکہ تمہاری اخلاقی قوتوں کے فرق اوراختلاف کے باوجود کوئی انسانی تعلیم سب انسانوں کے لئے یکساںمفید ہوسکتی ہے.یہ ضرورت بھی اللہ تعالیٰ ہی پوری کرسکتاتھا.جو انسان کی طبیعت اور اس کے اختلافات کا پیداکرنے والا ہے.اوراسے جانتاہے ورنہ جو انسان قانو ن بنائےگااپنے ذوق اوراپنے میلان کے مطابق قانو ن بنالے گا.اوراگر جماعت بنائے گی تواس جماعت کے میلانوں تک وہ تعلیم محدود رہے گی.صرف اللہ ہی کی دی ہوئی تعلیم ہوگی جس میں ہر طبیعت کے میلان اورہر فطرت کے تقاضے کا خیا ل رکھا گیاہوگا.اورہرمخفی ضرورت کوپوراکیاگیاہوگا.پس الہام کا آنا انسان کی روحانی ترقی کے لئے ضروری ہے.ورنہ اول تو انسان اپنی عقل سے روحانی ضرورتوںکوپوراکرہی نہ سکے گا.اوراگر ایک حد تک ضرورت پوراکرنے کاسامان کرے گابھی تووہ محدود ہوگا.اوروہ نہ توکسی انسان کی سب ضرورتوںکو پوراکرسکے گااورنہ تما م انسانوں کی بعض ضرورتوںکو پوراکرسکے گا.اس آیت کے آخر میں فرمایاکہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشان ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں یہ لفظ اس جگہ اس لئے استعمال فرمایا کہ مختلف الوان کی ضرورت پوراکرنے کاسوال خالص اخلاقی سوال ہو جاتا ہے اورا س کا براہ راست نصیحت سے تعلق ہے.فکر ،عقل اور تذکر کو مضمون کے ساتھ مناسبت یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فکر، عقل اورتذکر کو ہر آیت کے مضمون کی مناسبت سے نہیں بلکہ سارے مضمون کی مناسبت سے رکھا گیا ہے اوردرحقیقت تینوں لفظوں کاتعلق سارے ہی مضمون سے ہے صرف ان کو ان کے درجہ کے مطابق پھیلاکر سارے مضمون میں رکھ دیاگیاہے.پہلے فکر کو رکھا ہے.کیونکہ یہ پہلا ذریعہ اصلاح کا ہے.کیونکہ جب انسان نیک یا بد تغیر کی طرف جھکنے لگتا ہے.توپہلے فکر پیدا ہوتاہے پھر جب فکر کامل ہوجائے توعقل پیداہوتی ہے.یعنی انسان بدی سے رکنے لگتاہے.اوراس کے عمل میں اصلا ح شروع ہوتی ہے.جب یہ عملی اصلاح ہوجاتی ہے توتیسرادرجہ تذکر کاشروع ہوتاہے یعنی نیکی راسخ ہوجاتی ہے اورہرقدم پر انسان کو اس کافرض یاد آتا رہتا ہے.اورعقل کے مقام پر جس طرح اسے اپنے نفس کو روکنا پڑتا تھا.اب اس کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ نفس خود ہی نیکی کےاصو ل کو یاد رکھتا ہے اورنیکی اس کی طبیعت ثانیہ ہوجاتی ہے.
Page 44
وَ هُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ اوروہ ،وہ(پاک)ذات ہے جس نے سمند ر کو(بھی تمہاری )بے اجر ت کی خدمت پرلگارکھا ہے تاکہ تم اس میں سے تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا١ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ (مچھلی وغیرہ کا)تازہ گوشت کھائو.اوراس سے زیور(کاسامان )نکالو جسے تم (لوگ )پہنتے ہو.اور(اے مخاطب) مَوَاخِرَ فِيْهِ وَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تو اس میں کشتیوںکو پانی پھاڑتے (اورزورسے چلتے)ہوئے دیکھتاہے (جواس لئے چلتی ہیں کہ تم سمندری سفر طے تَشْكُرُوْنَ۰۰۱۵ کرو)اورتاکہ تم اس کے بعض اورفضل (بھی )تلاش کرو اورتاکہ تم (اس کا)شکر اداکرو.حلّ لُغَات.اَلطَّریُّ.طَرِیَ الْغُصْنُ واللَّحْمُ وَالثَّوْبُ (یَطْرٰی وَطَرُ وَیَطْرُ وْ، طَرَاوَۃً وطَرَاءَۃً وَطَرَاءً)کانَ طَرِیًّا.ہرچیز جو نئی ہو اوربناوٹ کے لحاظ سے تروتازہ ہو اُسے طَرِیٌّ کہتے ہیں.جیسے نیا کپڑا.گوشت جو تازہ ہو.اسی طرح درخت کی شاخ جو تازہ ہو (اقرب) پس لَحْمٌ طَرِیٌّ کے معنے ہوں گے تازہ گوشت.اَلْحِلیَۃُ.مَا یُزَیَّنُ بِہٖ مِنْ مَصُوْغِ الْمَعْدِنِیَّاتِ اَوِ الْحِجَارَۃِ الْکَرِیْمَۃِ.معدنیات اورقیمتی پتھروں سے بنے ہوئے زیورات جوزینت کے لئے پہنے جاتے ہیں.اس کی جمع حُلیٌّ آتی ہے.(اقرب) الفُلْکُ.اَلسَّفِیْنَۃُ.کشتی.یُذَکَّرُوَیُؤَنَّثُ یہ لفظ مذکر اورمؤنث دونوں طر ح استعمال ہوتاہے.(اقرب) مَوَاخِر.مَوَاخِرُ مَاخِرَۃٌٌّ کی جمع ہے.اورمَاخِرَۃٌ مَـخَرَ سے اسم فاعل کاصیغہ ہے مَـخَرَتِ السَّفِیْنَۃُ کے معنے ہیں جَرَتْ تَشُقُّ الْمَاءَ مَعَ صَوْتٍ.کشتی پانی کو چیرتی ہوئی چلی گئی اور اس کی آواز نکلتی تھی.وَقِیْلَ اِسْتَقْبَلَتِ الرِّیْحَ فِیْ جَرْیَتِھَا.اوربعض نے یہ معنے کئے ہیں کہ کشتی ہواکے رخ پر چلی.مَـخرَ السَّابِحُ کے معنے ہیں شَقَّ الْمَاءَ بِیَدَیْہِ تَیرنے والا اپنے دونوں ہاتھو ں سے پانی کو چیرتاہواتَیرا.اَلْفُلْکُ الْمَوَاخِرُالَّتِیْ تَشُقُّ الْمَاءَ مَعَ صَوْتٍ.وہ کشتیاں جو پانی کو ا س طور پر چیرتی ہوئی چلتی ہیں کہ اُن سے آواز پیداہوتی ہے.(اقرب) تفسیر.خشکی کی چیزوں کے مقابل تری کی چیزوں کا ذکر پہلی آیات میں خشکی کی چیزوں کا
Page 45
ذکر کیا تھا یاان چیز وں کا جن سے انسان خشکی پر بھی فائدہ اٹھا سکتاہے.اب تری کا ذکر کیا اورسمند کے مسخرہونے کا ذکر فرمایا.سمند رکے لفظ کو بھی تسخیر کے لفظ سے شروع کیا.کیونکہ سمند ر بھی انسان کے تصرف میں نہیں ہوتا.بلکہ انسان محض اس سے فائدہ اٹھاتاہے.مگررات، دن، سورج، چاند، ستاروںکی تسخیر کے ذکر میں مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ فرمایاتھا.سمندر کے سوا ستاروں کی تسخیر کے ساتھ بامرہ کا لفظ لگانے کا مطلب سمندر کے ذکر میں بِاَمْرِهٖ نہیں فرمایا.اس لئے نہیں کہ اس کی تسخیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوتی.بلکہ اس وجہ سے کہ اجرام فلکی سے فائدہ اٹھانے کے لئے انسان کچھ بھی کام نہیں کرتا.پس ان کی تسخیر کامل طور پر بِاَمْرِهٖ ہوتی ہے مگرسمندر سے فائدہ اٹھانے میں کشتی، جال وغیرہ انسان بناتاہے اس لئے وہاں امر کالفظ نہ رکھا.ورنہ یوں تو ہر کام بِاَمْرِهٖ ہی ہوتاہے.سمندر کی تسخیر کے ذکر کی وجہ سمندر کی تخلیق بھی انسانی ضرورتوں کے پوراکرنے کا ایک بہت بڑاذریعہ ہے.اس میں بہت سے خزانے محفوظ رہتے ہیں.جواس کے بغیر محفوظ نہ رہ سکتے تھے.مثلاً وہ پانی کاذخیر ہ جمع رکھتاہے.جہاںسے پھر سورج اس کو اُٹھا کرلاتا ہے.پھر اس کے ذریعہ سے سفروں میں سہولت ہوتی ہے.خشکی کے سفر سے وہ بہت زیادہ سستاہوتاہے.جوملک سمندر کے کنارہ پر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تجارتی اورسیاسی ترقی کرسکتے ہیں.کیونکہ سمندر کسی کے قبضہ میں اس طرح نہیں آسکتا جس طرح خشکی قبضہ میں ہوتی ہے.سمندر حریت کے قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اس طرح سمندر گویا حریت کے محفوظ رکھنے کاایک ذریعہ ہے.پس سمندر کی مثال دی کہ سمندر بھی تمہاری ضرورت کو پوراکرنے کے لئے بنایا ہے.اور اس میں بھی دیکھو کہ تمہاری غذا کاسامان رکھا ہے.مچھلی وغیرہ کاتازہ گوشت تم کو مل جاتاہے.اب کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہارے جسم کے لئے توخشکی تری میںسفر کی سہولتیں بہم پہنچائے مگر دین کے لئے وہ کچھ بھی نہ کرے.اور کیا پھر یہ اس سے بھی عجیب بات نہیں کہ تم دنیاوی سامانوں کو توشوق سے قبول کرولیکن روحانی سامانو ں کے وقت کہو کہ خدا تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمارے لئے روحانی ترقی کا کوئی سامان پیداکرے.صداقتیں اسی وقت فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب وہ صاف کرکے استعمال کے قابل بنا دی جائیں اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسانی ضرورتوںکوپانی پوراکرتاہے اوریہ پانی زمین میں سمندر کی صورت میں موجود بھی ہے.لیکن باوجود اس کے اس پانی سے انسان پینے کافائدہ نہیں اٹھاسکتا.کھیتوں کو سیراب کرنے کافائد ہ نہیں اٹھا سکتا.مگر اللہ تعالیٰ اس پانی سے مچھلی جیسی اعلیٰ غذاپیداکرتا ہے اوراس پانی کو سورج کے ذریعہ سے اٹھا کر
Page 46
پینے کے قابل بنادیتا ہے.پس صداقتوں کادنیا میں موجود ہوناکافی نہیں.وہ اسی وقت مفید ہوتی ہیں جب ان کو صاف کر کے اللہ تعالیٰ انسانی روح کے استعمال کے قابل بنادے.وَتَسْتَخْرِجُوْامِنْہُ حِلْیَۃً.یعنی موتی وغیرہ اسی ناقابل استعمال چیز سے ہی پیدا ہوتے ہیں جن سے تم زیور بناتے ہو.اسی طرح اس میں کشتیاں چلتی ہیں جن سے سفر کی سہولت بھی حاصل ہوتی ہے اورتجارت بھی ترقی کرتی ہے.جس طرح جانوروں کے متعلق فرمایاتھا کہ تم کو بھی لے جاتے ہیں اور تمہارے اسباب اورسامان بھی.وہی کشتیوں کے متعلق فرمایا کہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں اور تمہارے تجارتی سامان بھی لے جاتی ہیں.تجارتی سامان جس طرح ارزاں طور پر سمند رمیں لے جایا جاسکتاہے خشکی میں نہیں.اسی وجہ سے سمندری کناروں کے لوگوں کی تجارت زیادہ چمک جاتی ہے.وَ اَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَ اَنْهٰرًا وَّ اوراس نے زمین میں (بہت سے)محکم پہاڑ (گاڑ)رکھے ہیں تاکہ وہ تمہیں چکر میں نہ ڈالے اور(اس نے سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَۙ۰۰۱۶ تمہارے لئے ) کئی دریا (چلائے ہیں )اور کئی (خشکی کے )راستے (بھی بنائے)ہیں تاکہ تم (آسانی سے اپنی منزل مقصود تک )راہ پاسکو.حلأ لُغَات.اَلْقٰی اَلْقَاہُ اِلَی الْاَرْضِ کے معنے ہیں طَرَحَہُ.اس کو زمین کی طرف پھینکا.اَلْقٰی اِلَیْہِ الْقَوْلَ وَبِالْقَوْلِ:اَبْلَغَہُ اِیَّاہُ.کوئی بات اُسے پہنچائی.اَلْقَی الْمَتَاعَ عَلَی الدَّابَۃِ: وَضَعَہٗ.سامان کو جانورپر لادا.اَلْقٰی فِیْہِ الشَّیْءَ :وَضَعَہٗ.کسی چیز کو کسی جگہ رکھا.اَلْقٰی اِلَیْہِ السَّمْعَ:اَصْغٰی.اس کی بات سننے کے لئے پوری توجہ کی.(اقرب) رَوَاسِیَ.رَوَاسِیَکے لئے دیکھو سورۃ رعد آیت ۴.الرَّوَاسِیَ.اَلْجِبَالُ الثَّوَابِتُ الرَّوَاسِخُ (اقرب) مضبوط پہاڑ.ان معنوں کے لحاظ سے رَوَاسِیَ کا مفرد نہیں آتا.اَنْ تَمِیْدَبِکُمْ.تَمِیْدُ مَادَ سے مضارع مؤنث غائب کاصیغہ ہے.اور مَادَالشَّی ءُ کے معنے ہیں.
Page 47
تَحَرَّک و زَاغَ.کسی چیز نے حرکت کی اورایک طرف پر مائل ہوگئی.یُقَالُ مَادَتْ بِہِ الْاَرْضُ: دَارَتْ اور مَادَتْ بِہِ الْاَرْضُ کامحاورہ بول کریہ معنی مراد لیتے ہیں کہ زمین نے اپنے چکر کھانے کے ساتھ ا سے بھی چکر دیا.السَّرَابُ:اضْطَرَبَ سراب نے حرکت کی.(اقرب)پس اَنْ تَمِیْدَبِکُمْ کے معنے ہوں گے کہ اس ڈر سے کہ زمین متحرک ہوتے ہوئے تمہیں چکر میںنہ ڈالے.ا س ڈرسے کہ تم کو اضطراب میں نہ ڈالے.ہماری زبان اور عربی زبان میں فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ فلاں کام نہ ہوجائے.اورعرب کہتے ہیں اس ڈر سے کہ ایسا ہو جائے.گویا وہ ’نہ‘ کو محذوف کردیتے ہیں.تفسیر.انہار، سبل اور رواسی کے ساتھ القی کے لفظ کا استعمال اس آیت میں اَلْقٰى کالفظ استعمال کرکے اس کے بعد رَوَاسِیَ، اَنْھَارًا اورسُبُلًا تین چیزوں کو بیان فرمایا ہے.گویاسب کاعامل اَلْقٰى کالفظ ہے.اَلْقٰى کے عام معنے پھینکنے کے ہوتے ہیں.اگران معنوں کو مدنظر رکھاجائے توآیت کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ زمین میں پہاڑ دریا اورراستے پھینکے.اَلْقٰى کے عام معنوں کے مدنظر اس پرایک اعتراض اوراس پر اعتراض ہوتاہے کہ پہاڑ توزمین میں سے نکلے ہیں اوردریا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پانی لے جاتے ہیں اورراستے چلنے کی جگہ کانام ہے.پھر ان کے پھینکنے کے کیا معنے ہوئے.بعض نے اس کا جواب یہ دیاہے کہ اَلْقٰى کا لفظ صرف رَوَاسِيَ کے ساتھ لگتاہے.باقی دولفظوں سے پہلے جعل کالفظ محذوف ماناجائے گا.اوراس کے یہ معنے ہوں گے کہ پہاڑ پھینکے اوردریا اورراستے بنائے.دونوں اشیا ءکی مشارکت کی وجہ سے دونوں کا ایک ہی فعل کا عامل ہونا اس میں کوئی شک نہیں کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب دواشیاء ایک ساتھ بیان ہوتی ہیں.تومشارکت کی وجہ سے ایک ہی فعل کو دونوں کاعامل بنادیاجاتا ہےاوردوسرافعل محذوف سمجھا جاتا ہے.(فتح البیان زیر آیت ھذا) جیسے کہ ایک عرب شاعر کاشعر ہے قَالُوْا اقْتَرِحْ شَیْئًا نُجِدْ لَکَ طَبْخَہٗ قُلْتُ اطْبُخُوْا لِیْ جُبَّۃً وَّ قَمِیْصَا (کلیات ابو البقاء فصل المیم) یعنی کہنے والوں نے کہا کہ آپ ہم سے کچھ خواہش کریں.توہم آپ کے لئے کوئی کھانااچھی طرح تیار کریں گے.میں نے کہا کہ ہاں کھانابھی پکائواورجُبّہ اورقمیص بھی پکائو.اس جگہ پکائو کالفظ ہی جُبّہ اورقمیص کے ساتھ لگادیاگیا
Page 48
قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ قُلِ اللّٰهُ١ؕ قُلْ تو (ان سے) کہہ( کہ بتاؤ) آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے (اس کا جواب وہ توکیا دیں گے) تو( خود ہی) کہہ اَفَاتَّخَذْتُمْ۠ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ دے (کہ) اللہ (اور پھر )تو(ان سے) کہہ( کہ) کیا پھر( بھی) تم نے اس کے سواء اور( اور اپنے) مددگار بنا نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا١ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ١ۙ۬ رکھے ہیں.جو (خود) اپنے لئے (بھی) کسی نفع (کو حاصل کرنے) کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ کسی نقصان (کو اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ١ۚ۬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ روکنے) کی (اور ان سے )کہہ( کہ) کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر (ہو سکتا) ہے یا کیا تاریکی؎ اور روشنی برابر( ہو سکتی) خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ١ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ ہے یا کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک تجویز کئے ہیں جنہوں نے اس کی مخلوق کی طرح (کچھ) پیدا کیا ہے.کہ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۰۰۱۷ (جس کی وجہ سے اس کی اور دوسروں کی) مخلوق ان کے لئے مشتبہ ہوگئی ہے ؟ تو (ان سے) کہہ (کہ) اللہ (ہی) ہر ایک چیز کا خالق ہے اور وہ کامل( طور پر) یکتا (اور ہر ایک چیز پر) کامل اقتدار رکھنے والا ہے.حلّ لُغَات.رب کی تشریح کے لئے دیکھوالرعد آیت نمبر۲جلد ھٰذا.اَوْلِیَآءَ.وَلِیٌّ کی جمع ہے اور اَلْوَلِیُّ کے معنے ہیں اَلْمُحِبُّ، اَلصَّدِیْقُ.دوست.اَلنَّصِیْرُ.مددگار.(اقرب) یَمْلِکُوْنَ مَلَکَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور مَلَکَ کے معنے ہیں اِحْتَوَاہُ قَادِرًا عَلَی الْاِسْتِبْدَادِبِہِ کسی چیز پر قادرانہ طور پر قبضہ کیا.مَلَکَ عَلَی الْقَوْمِ.اِسْتَوْلٰی عَلَیْہِمْ.کسی قوم پر غالب ہوا.عَلَی فُلَانٍ اَمْرَہٗ.اسْتَوْلَی عَلَیْہِ کسی کے کام کا متولّی ہوا.اَلْخِشْفُ اُمَّہٗ قَوِیَ وَقَدَرَ اَنْ یَّتْبَعَہَا.ہرن کا بچہ توانا و مضبوط ہوکر اس قابل ہو گیا
Page 49
کہ وہ اپنی ماں کے پیچھے چل سکے.(اقرب) پس لَا يَمْلِكُوْنَ کے معنے ہوں گے وہ قادر نہیں ہوسکتے.وہ طاقت نہیں رکھ سکتے.اَلْوَاحِدُ بِمَعْنَی الْاَحَدِ اَیْ اَلْمُنْفَرِدُ الَّذِیْ لَانَظِیْرَ لَہٗ اَوْلَیْسَ مَعَہٗ غَیْرُہٗ.ایسا یکتا کہ جس کا کوئی نظیر نہ ہو یا اس کا کوئی شریک نہ ہو.اور انہی معنوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے.(اقرب) قَھَّارٌ.قَھَرَہٗ.قَھْرًا.غَلَبَہٗ.قَھَرَ کے معنے ہیں.کسی پر غالب آیا.(اقرب) اور اَلْقَہَّارُ مبالغہ کا صیغہ ہے اس کے معنے ہوں گے.بہت غالب.تفسیر.جتنے لوگوں کو دنیا نے خدا بنایا ان کی زندگی دکھ میں گزری یہ عجیب خدا کی قدرت ہے کہ جتنے لوگوں کو دنیا نے خدا بنایا ان کی زندگی دکھ اور تکلیف میں ہی گزری ہے.حضرت مسیح کو ملک چھوڑنا پڑا اور مختلف تکالیف کا سامنا ہوا.حضرت حسینؓ تو شہید ہی کر دیئے گئے.رام چندر جی بھی مصائب میں مبتلا رہے.لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ میں بتایا ہے کہ جب وہ اپنی جانوں کی بھی حفاظت نہ کرسکے تو تم کو کیا نفع پہنچائیں گے.هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوسکتے ہیں.یعنی تم لوگوں کو اپنی کثرت پر ناز ہے مگر یہ تو سوچو کہ کیا ہمیشہ کثرت مفید ہوا کرتی ہے.بہت سے اندھوں کا اجتماع قوت کا موجب ہوتا ہے یا ضعف کا.ایک آنکھوں والا ہزاروں اندھوں پر غالب ہوتا ہے.ایسا ہی اس نبی اور اس کے متبعین کو خدا سے علم ملتا ہے اور تمہارے منصوبوں اور تدبیروں سے خدائی وحی اسےآگاہ کر دیتی ہے.پس اس کی مثال بینا کی ہے مگر تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ اس کی طرف سے کیا کیا تدابیر کی جارہی ہیں.کیونکہ اس کی تائید میں اکثر کوششیں خدا تعالیٰ کی طرف سے قانونِ قدرت کے مخفی اثرات کے ذریعہ سے ہورہی ہیں.جن سے تم بالکل ناواقف ہو.پھر سوچو تو سہی کہ تم اس کا اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کیونکر کرسکتے ہو؟ یہ تھوڑے ہیں تو کیا ہوا ہیں تو آنکھوں والے.هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ.اسی طرح فرمایا ظلمات اور نور کا بھی کوئی مقابلہ نہیں.تھوڑی سی روشنی سارے کمرے کا اندھیرا پاش پاش کردیتی ہے.ظلمات عدم نور کا نام ہے اور نور وجود کا.اور وجود کے سامنے عدم کی حیثیت ہی کیا ہے.یعنی تمہارے پاس الٰہی تعلیم نہیں.اس کے پاس ہے.پس تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ.اس کی تعلیم کی بنیاد تو حقائق پر ہے اور تمہاری تعلیم کی بنیاد صرف جہالت اور انکار پر.اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ.یہ بات مشرکین کے سامنے بطور اعتراض پیش کی گئی ہے یعنی تم باوجود مشرک ہونے کے بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں کرسکتے کہ معبودانِ باطلہ نے کوئی خلق کی ہے اور وہ خدا کی خلق سے مشابہ ہے.چنانچہ مکہ کے مشرکین اس بات کی جرأت نہ کرسکے.گو بعض اور ممالک کے مشرک اپنے
Page 50
اورگویا آسمان سے دنیا کی سطح پر ان کو پھینک دیا ہے اوروہ دنیا میں بکھر گئے ہیں.ایک ایسی صداقت ہے جوعلم الٰہی کے ذریعہ سے ہی ظاہر ہوسکتی تھی.اب جبکہ دنیا قریباً سب کی سب دریافت ہوچکی ہے.یہ صداقت کیسی کھل چکی ہے کہ دنیا کے تمام براعظموں میں پہاڑ دریا اورراستے پائے جاتے ہیں.اور سب دنیا اس نعمت سے حصہ لے رہی ہے.پس القٰی کے لفظ کو ان تین اشیاء کے متعلق مجازاً استعمال کر کے قرآن کریم نے ایک نئے معنے پیداکردیئے ہیں.اورایک نئی صداقت ظاہر کردی ہے.اور دوسرے مقامات پر جَعَلَ کے لفظ کے استعمال سے ان نادانوں کامنہ بھی بند کردیا ہے جو اس لفظ سے دھوکاکھاکر یہ کہہ سکتے تھے کہ قرآن کے روسے پہاڑ دریا اورراستے کہیں باہرسے لاکر زمین پر پھینک دئے گئے ہیں.راستوں کے بنانے پر ایک سوال اور اس کا جواب ایک اورسوال اس جگہ ہوسکتا ہے کہ پہاڑ اور دریا تو قانون قدرت بناتا ہے.ان کے ساتھ راستوں کاکیوں ذکر کیا ہے.وہ توانسانوں کے بنائے ہوئے ہیں.اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ انسانی بنائی ہوئی سڑکوں کا ذکر نہیں وہ تودنیا کے ہرحصہ میں نہیں ہوتیں.اس جگہ صرف ان راستوں کا ذکر ہے جو طبعی ذرائع سے بن جاتے ہیں.مثلاً دریائوں کی وجہ سے یاپہاڑوں کی وجہ سے یاجنگلوں کی وجہ سے.اوریہی راستے ہیں جوعام ہیں اورجن سے سب دنیا فائدہ اٹھاتی ہے خصوصاً پرانے زمانہ میں فائدہ اٹھاتی تھی.افغانستان اورہندوستا ن کی سرحد سینکڑوں میل تک ملی ہوئی ہے مگرہرحصہ اس کاراستہ نہیں.راستے صرف چند ہیں.جو پہاڑی درّوں کی مناسبت سے بن گئے ہیں.یہی حال چینی ہندوستانی سرحد کااور ہندوستانی برہمی سرحد کاہے.اورسب ممالک کا یہی حال ہے.اصل بات یہ ہے کہ شہروں کے درمیان تو سڑک کابنانااپنے اختیار میں ہوتاہے مگر علاقوں اورملکوں کے درمیان سڑکوں کا بنا نا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا.بلکہ اس کاتعلق دریائوں سے پار ہونے کی سہولت ،پہاڑوں کے درّوں یاجنگلوں کے کناروں سے ہوتاہے.اورہمیشہ سے دنیا ان راستوں کواستعمال کرتی چلی آئی ہے.گوان جگہوں پر کوئی سڑک نہیں بنی ہوئی تھی.صرف قدرتی سہولتوں کی وجہ سے لوگوں نے ان راستوں کو اختیار کرلیا تھا.اورہزاروں سالوں سے آج تک وہ راستے کام دے رہے ہیں اوران کے ذریعہ سے پرانے زمانہ میں تجارت ہوتی تھی.ایک ملک سے دوسرے ملک پرچڑھائی ہوتی تھی.ہندوستان پر جس قدر حملے شمال پر ہوئے ہیں دیکھ لو صرف چنددرّوں سے ہوئے ہیں(تاریخ صوبہ سرحد از محمد شفیع صاحب اشاعت اول جون ۱۹۸۶ء ناشر یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر باز ار پشاورصفحہ ۵۲،۵۵).ہندوستان میں آریہ قوم پھیلی ہے.توپہلے اسی طبعی راستہ پر چل کر جو پنجاب کے دریائوں کے ساتھ ساتھ چلتاتھا.اورپھراس راستہ پر چل کر جو جمناگنگا کے کنار ے پرجاتاتھا.یاان
Page 51
راستوں پرچل کر جو ہمالیہ اور دوسرے پہاڑوںیاکجلی بن کے دامن پر قدرت کے ہاتھو ں سے تیار کیا گیاتھا.اس زمانہ میں راستہ کے لئے طبعی نشانوں کاموجود ہوناضروری ہوتاتھا.جن کی وجہ سے لوگ مسافتوں اورجہات کا اندازہ لگاسکیں.اسی طرح غذاکامہیاہوناضروری ہوتاتھا.پس پہاڑوں کے دامنوں،جنگلوں کے ساتھ ساتھ اوردریائوں کے کناروں کے ساتھ ساتھ لوگ بالعموم سفر کرتے تھے اوریہ گویاطبعی راستے تھے جن سے دنیا کے تعلق قائم تھے.اوراس آیت میں انہی راستوں کا ذکر ہے نہ کہ مقامی سڑکوں کاجومختلف شہروںکو آپس میں ملاتی ہیں اس بیان سے اس امر کی حکمت بھی ظاہرہوجاتی ہے کہ کیوں ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کرکے بیان کیاگیا ہے.راستوں سے مراد دریاؤں کے راستے اس کے علاوہ راستوں سے مراد وہ راستے بھی ہوسکتے ہیں جن پر دریاچلتے ہیں.اوراگراللہ تعالیٰ زمین میں ایسے خلال یانشیب نہ پیداکرتا جن میں دریائوں کاپانی سکڑ کرچلتاہے توسب زمین پر پانی ہی پانی ہوتا اوردنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی.پہلی اشیاء کو بیان کرنے کے بعد سبل ،انہار اور رواسی کے بیان میں حکمت پہلی اشیاء کے ذکر کے بعد ان اشیاء کو الگ کیوں بیان کیاگیاہے ؟ اس میں یہ حکمت ہے کہ پہلے متفرق چیزوں کا ذکر تھا.اب اس آیت میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو خزانہ کو جمع رکھتی ہیں.پہاڑ برف کے ڈھیر جمع رکھتے ہیں درخت اور جڑی بوٹیوں کے ذخیرے رکھتے ہیں.دریاپہاڑوں سے پانی لے کر سال بھر تک پانی ملک کو مہیاکرتے ہیں.اورطبعی راستے ان جگہوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے انسان کی مدد کرتے ہیں.اگرپہاڑصرف ایک بلند ٹیلاہوتے اوراس طرح تدریجی طریق پر بڑھنے والی بلندیا ں نہ ہوتے توانسان ان کی چوٹیوں تک کس طرح پہنچ سکتا تھا.اگردریا ایک پھیلاہواپانی ہوتے توان سے دنیا فائد ہ نہیں اٹھاسکتی تھی.اُلٹاان سے نقصا ن ہوتاکہ قابل کاشت زمینوں کو وہ پانی کے نیچے چھپائے رہتے اورچلنا پھرنا لوگوں کے لئے مشکل ہوجاتا.پہاڑوں اور دریاؤں کا خاص قانون کے ماتحت پھیلنا پس پہاڑو ں اوردریائوںسے فائدہ اسی صورت میں اٹھایاجاسکتاہے کہ وہ خاص قانون کے ماتحت پھیلیں یاان تک پہنچنے کے لئے ان کے ساتھ ساتھ راستے ہوں جن پر چل کر انسان ان کے فوائد سے متمتع ہوسکے.اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق اس آیت کا پہلی آیات سے تعلق ایک تونعماء الٰہی کے شمار کے لحاظ سے ہے اوریہ بتایاگیا ہے کہ جب تمہارے مادی فوائد کے لئے یہ کچھ سامان پیداکئے گئے ہیں توتمہاری روحانی ضرورتوںکو اللہ تعالیٰ کس طرح نظرانداز کرسکتاتھا.دوسرے یہ بتایاگیا ہے کہ انسانی تدابیر صرف ایک وقت کی ضرور ت
Page 52
کوپوراکرسکتی ہیں.اللہ ہی ہے جو مستقل ذخائر کے جمع رکھنے کے سامان پیداکرتاہے.باولیاں کب تک پانی دے سکتی ہیں اورکہاں تک.دریاہی ہیں جو ساراسال پانی دیتے ہیں اورملکوں کے ملک ان سے سیراب ہوتے ہیں.اسی طرح پہاڑ ہیں جو ملکوں کی ضروریات کو پوراکرتے ہیں.اورساراسال قسما قسم کی ضروری ادویہ اورپھل پھو ل اورنہ ختم ہونے والے ذخائرلکڑی کے ان سے ملتے ہیں.اورپھر یہ بڑے راستے ہی ہیں کہ جودنیا کے درمیان تعلق قائم کررہے ہیں.مختلف زمانوں اور مختلف فطرتوں کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کلام الٰہی کی ضرورت پس اسی طرح روحانی ضرورت کو پوراکرنے کے لئے ایسے کلام کی ضرورت ہے جو صرف ایک وقت کے لوگوں یا چند لوگوں کے فائدہ کے لئے نہ ہو.بلکہ مختلف فطرتوں اورمختلف زمانوں کی ضرورت کو پوراکرنے والاہو.اورجس کے ذریعہ سے دنیا روحانی مسافت طے کرسکے.یعنی ایک نبی کے زمانہ سے اس کے بعد کے نبی کے زمانہ تک پہنچانے کی اس میں قابلیت ہو.یعنی اس میں ایسا ارتقاء ہو کہ فطرت انسانی اس پر چل کر اگلے روحانی ملک میں یعنی بعد میں آنے والے نبی کی تعلیم تک پہنچنے کی قابلیت پیداکرلے.انسان کو کیا معلوم ہے کہ سویادوسو سال بعد انسانی دما غ نے کیا ترقی کرنی ہے کہ وہ اس کے مطابق ذہنوں کو روشنی پہنچانے کے سامان کرے.یہ سفرتوالٰہی بنائے ہوئے راستہ پر ہی طے ہو سکتا ہے.جوانسانی دماغ کو برابر ترقی دئے چلاجاتاہے.یہی وجہ ہے کہ مختلف فلسفے ایک شاہراہ پر گامزن نہیںہوتے.بلکہ کبھی آگے قد م بڑھاتے ہیں اور کبھی پھر واپس صدیو ں کے فلسفہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں.لیکن اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیمات نبیوں کی معرفت انسانوں کو ایک ہی شاہراہ پر آگے ہی آگے بڑھاتی چلی گئی ہیں اوران میں کسی جگہ بھی رجعت قہقری پیدا نہیں ہوئی.وَ عَلٰمٰتٍ١ؕ وَ بِالنَّجْمِ اور(ان کے علاوہ اس نے)کئی (اور)علامات بھی (قائم کی ہیں )اورستاروں کے ذریعہ سے (بھی ) هُمْ يَهْتَدُوْنَ۰۰۱۷ وہ (لوگ)راہ پاتے ہیں.تفسیر.عَلٰمٰتٍ کا عطف اَلْقٰی پر ہے عَلٰمٰتٍ کاعطف بھی اَلْقٰی پر ہی ہے اوراس میں بھی
Page 53
اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا بھر میں سطح زمین یکساں اورمشابہ نہیں.بلکہ نشیب و فراز،پانی ،خشکی جنگل اوربیابان زمینوں کی مٹی کے فرق اس قدر ہیں کہ ان کے ذریعہ سے انسان راستہ معلوم کرلیتا ہے.اگر سب دنیا ایک ہی شکل کی ہوتی توانسان کولہوکے بیل کی طرح ایک ہی جگہ چکر لگاتارہتا.ظاہری ستاروں کے بالمقابل روحانی ستارے یہ توزمین پر راستوں کے معلوم کرنے کاذریعہ ہے.ایک آسمانی ذریعہ بھی ہے جورات کی تاریکی اورسمندر میں کام آتا ہے اوروہ ستارے ہیں.ان کو دیکھ کر انسان اپنے راستے کو معلوم کرتا ہے.یہی حال روحانی سفر کاہے اس میں بھی علامات ہیں.یعنی روحانی ترقی کے مدارج میں امتیاز ی نشان پیداکئے گئے ہیں جس کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتاہے کہ آگے کو کون ساراستہ جاتاہے اورپیچھے کو کونسا.اسی طرح ستاروں کی طرح انبیا ء کاوجود ہے کہ ان کے مقام سے بھی انسان روحانی سیر میں راستہ پاتا ہے.اورہرنبی کو جودوسرے نبی سے نسبت ہوتی ہے.اس کے ذریعہ سے وہ روحانی سیر میں مدد دیتا ہے.جس طرح ایک ستارہ اپنے مقام سے دوسرے ستارے کے مقام کی طر ف رہنمائی کرتاہے.اسی طرح ہرنبی اپنی تعلیم سے دوسرے نبی کی خبر دیتاہے اوراس طرح انسان اپنے ایما ن میں آگے ہی آگے بڑھتاچلاجاتاہے.موسیٰ ؑنے اپنے بعد آنے والے نبی کی ا س نے اپنے بعد کے نبی کی اوراس نے اپنے بعد کے نبی کی خبر دی.اورگویا ہرستارہ دوسرے ستارے کی طرف رہنمائی کرتا گیااورسب ستاروں نے سورج کی یعنی محمدرسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کی طرف رہنمائی کی.جس سے انسان کو روحانی سفر کے طے کر نے اورمرکز روحانیت کے مقام تک ہدایت پانے کا موقعہ مل گیا.اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ١ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ۰۰۱۸ پھر (بتائو تو سہی کہ )کیا جو پیداکرتا ہے وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو(کچھ بھی )پیدا نہیں کرتا کیاتم پھر (بھی) نہیں سمجھتے.تفسیر.آیت اَفَمَنْ يَّخْلُقُ میں اس کی ترتیب کے متعلق ایک سوال اور مفسرین کا جواب آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا جس نے پیدا کیاہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس نے پیدا نہیں کیا.اس پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایاہے کہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ کیاجو پیدا نہیں کرتا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیداکرتاہے (کشاف زیر آیت ھذا)کیونکہ مقابلہ میں ادنیٰ کو اعلیٰ کے مقابل پر رکھتے ہیں نہ کہ اعلیٰ کو ادنیٰ کے مقابل پر.طاقت کے اظہار کے لئے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کیا بچہ پہلوان کی طرح ہوسکتا ہے.مگریہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا پہلوان بچہ کی طرح
Page 54
ہو سکتا ہے.یہ اعتراض بالکل درست ہے.اگر اس آیت میں طاقت کا اظہار مقصود ہوتا توضرور یہی کہا جا تاکہ کیا جو نہیں پیداکرتا وہ پیداکر نےوالے کے برابرہوسکتا ہے.مگراس جگہ یہ مراد ہی نہیں.علامہ زمخشری اس سوال کو بیان کر کے اس کایہ جواب دیتے ہیںکہ مشرک خدا تعالیٰ کی صفات غیراللہ کودے کر گویا اللہ تعالیٰ کوبھی ایک مخلوق قراردیتے تھے.اس لئے یہ فرمایاکہ اس طرح خدا تعالیٰ پر الزام لگتا ہے تمہارے جھوٹے معبودوں کا درجہ تونہیں بڑھتا.خدا تعالیٰ کا ہی درجہ گھٹاناپڑتا ہے مگر کیا خدا تعالیٰ ان ادنیٰ وجودوں کے برابر ہو سکتا ہے.میرے نزدیک یہ جواب اس قدر معقو ل نہیں جیسا کہ اعتراض جو انہوں نے اوپر اٹھایا ہے.آیت اَفَمَنْ يَّخْلُقُ میں اس کی ترتیب کے متعلق مشکل کا حل میرے نزدیک اس سوال کا جواب اس ترتیب کو مدنظررکھ کردیاجاسکتاہے جو میں نے گذشتہ آیات میں بتائی ہے.اصل مضمون جیساکہ میں بتاچکاہوں یہ تھا کہ کیا خدا تعالیٰ کو کسی الہا م بھیجنے کی ضرورت ہے؟ مشرک لوگ اپنے معبودوں کی نسبت یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کے معبود اس لئے الہام نازل نہیں کرتے کہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں بلکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے.نہ انہوں نے کوئی دنیو ی نعمت انسان کو دی ہے نہ دینی نعمت دینے کی توفیق ہے.پھر تم کس طرح سمجھتے ہوکہ خدا تعالیٰ بھی انہی کی طرح ہوجائے.حالانکہ اس میں توالہام بھیجنے کی طاقت ہے.پس جس طرح اس نے دنیوی نعمتیں دی ہیں وہ روحانی نعمتیں بھی دیتاہے.تم چاہتے ہوکہ وہ بھی تمہارے خیالی معبودوں کی طرح بے بس ہو کر بیٹھ جائے مگر وہ تو زندہ خدااورطاقتو رہے.اوراس نے ہزاروں سامان دنیوی ترقی کے پیداکئے ہیں.پس وہ تمہارے معبودوں کی طرح روحانی ترقی کے طریق بتانے میں کیوں کوتاہی کرے.تمہارے معبودوں کا ایسانہ کرنا ان کی علّو شان کی وجہ سے نہیں بلکہ معذوری کے سبب سے ہے اورخدا تعالیٰ معذورنہیں.اس لئے وہ کلام بھیجتا رہا ہے اوربھیجتارہے گا.چنانچہ اگلی آیت بھی انہی معنوں کی تصدیق کرتی ہے.وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ اوراگر تم اللہ( تعالیٰ )کے احسان شمار کرنے لگو.تو(کبھی )تم ان کا احاطہ نہ کرسکو گے.اللہ( تعالیٰ)یقیناً بہت (ہی) رَّحِيْمٌ۰۰۱۹ بخشنے والا (اور)باربار رحم کرنے والا ہے.تفسیر.دنیاوی نعمتوں کے ذکر سے روحانی نعمتوں کی طرف اشارہ یعنی اللہ تعالیٰ کی
Page 55
نعمتیں گننا چاہو تب بھی گن نہیں سکتے.پھر جس طرح اس نے یہ دنیوی نعمتیں نازل کی ہیں کیوں روحانی نعمتیں نازل نہ کرے.اورمعبودان باطلہ کی طرح جوکوئی طاقت نہیںرکھتے گونگا ہوکر بیٹھ رہے.دوسرے فرمایا کہ وہ غفو ر رحیم ہے اگر وہ ہدایت نہ بھیجے تو کمزورو ں کی معافی اورقابل لوگوں کی عزت کے بڑھانے کے سامان کس طرح پیداہوسکتے ہیں.اگر وہ ہدایت بھیجنے سے کوتاہی کرے توساتھ ہی اس کی غفور اوررحیم کی صفات بھی معطل ہوجاتی ہیں.پس وہ ایسانہیں کرسکتا.وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ۰۰۲۰ اورجوکچھ تم چھپاتے ہو اورجو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ (تعالیٰ)اس (سب)کوجانتا ہے.تفسیر.اب ایک اوردلیل دیتا ہے کہ کیوں انسان یا اُن کے معبودان باطلہ ہدایت کاسامان بہم نہیں پہنچاسکتے اوراللہ تعالیٰ ہی ایسا کرسکتاہے.فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ ظاہر اورمخفی طاقتوں کو جانتا ہے.ان شبہات کو بھی جانتا ہے جن کو تم بیان کرتے ہو اوران کو بھی جن کو تم چھپاتے ہو.پس ہدایت کاکام بھی وہی کرسکتا ہے.انسانی ہدایت کے لئے دو امور کی واقفیت کی غرض یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی ہدایت کے لئے دوامورکا ہوناضروری ہے.ایک تویہ کہ انسانی فطرت کی گہرائیوں سے کامل واقفیت ہو.کیونکہ جب تک ظاہری و باطنی قوتوں کا علم نہ ہو صحیح راہنمائی نہیں کی جاسکتی اورساری قوتو ں کے نشوونما کا سامان نہیں کیا جاسکتا.دوسری بات یہ ضروری ہے کہ دلوں کے خیالات کا علم ہو.کیونکہ ہزاروں لاکھو ں انسان اپنی قوم کے ڈر سے اپنے دلی شبہات بیان نہیں کرسکتے پھر جب ان کی مرض کاعلم نہ ہو توعلاج کرنے والا علاج کس طرح کرسکتا ہے.مثلاً اس زمانہ میں سینکڑوں تعلیم یافتہ ہیں جو درحقیقت الہام کے وجود سے منکرہیں.اگر ان کے سامنے الہام جاری ہونے کا مسئلہ پیش کیاجائے تووہ قوم کے ڈر سے یہ تونہیں کہتے کہ الہام کاوجود ہی کو ئی نہیں اورسب مدعیان الہام یاجھوٹے تھے یادھوکا خوردہ.پس اس کی بجائے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے بعد الہام کی کیا ضرورت ہے.اسی طرح نئی تعلیم کے دلدادوں میں سے ہزاروں لاکھو ںکو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد نہیں.مگر جب ان سے خدا تعالیٰ کے متعلق بات کی جائے تویہ کبھی نہ کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نہیں ہے بلکہ دوسری قسم کی باتیں کریں گے کہ خدا تعالیٰ توہےمگر اسے کیاضرورت ہے کہ دنیا کے معاملات میں دخل دے.پس دل میں نیکی پیداکرنی چاہیےخدا تعالیٰ خوش ہوجائے گا.غرض تصوف کے جھو ٹے مسائل کی
Page 56
آڑ لے کر وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کے جوئے سے آزاد ہوناچاہیں گے.مگرقوم کے ڈر سے یہ ظاہرنہ ہونے دیں گے کہ درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے ہی منکر ہیں.مصلح کے لئے انسانی فطرت کی گہرائیوں کی کامل واقفیت اور دلوں کے خیالات کا علم ہونا ضروری ہے اب اس قسم کے دلی شبہات کو اگر مصلح نہیں جانتاتووہ ان امورکے متعلق دلائل دیتا رہے گا جواصل میں خرابی کاموجب نہیں.بلکہ دھوکا دینے کے لئے صرف منہ سے بیان کئے جاتے ہیں.لیکن جو دل کے عیب کاواقف ہےوہ منہ کی باتوں کو نظرانداز کرکے اس شبہ کے ازالہ پر زوردے گاجو دل میں چھپایاگیا ہے اوراصلاح میں کامیاب ہوجائے گا.اوردل کی باتوں کاعلم چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے جس طرح صرف وہی انسانی قوتوں کا مکمل علم رکھتا ہے.اس لئے ہدایت نامہ بھیجنا بھی اس کے شایان شان ہے اوراسی کا بھیجاہو اہدایت نامہ دنیا کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے.اس دعویٰ کاعملی ثبوت قرآن کریم کاوجود ہے.اس میں تمام انسانی قوتوں کی راہنمائی کے سامان موجود ہیں اورانسان کی مخفی سے مخفی قوتوں کو ابھارنے کے لئے تعلیم موجود ہے.اسی طرح اس میں ہرانسانی شبہ کا جواب موجود ہے.حتّٰی کہ جو شبہات سائنس کی ترقی کی وجہ سے آج کل کے زمانہ میں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیںاورجن کو اکثر آدمی اپنی قوم کے ڈر سے زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں قرآ ن کریم نے انہیں بھی بیان کیاہے اوران کا جواب بھی دیاہے.وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّ هُمْ اوراللہ (تعالیٰ)کے سوا جن (معبودان باطلہ ) کو وہ پکارتے ہیں وہ کچھ (بھی )پیدا نہیں کرسکتے اور(اس سے بھی يُخْلَقُوْنَؕ۰۰۲۱ بڑھ کر یہ کہ )وہ خود پیداکئے جاتے ہیں.تفسیر.اس جگہ یہ خیال مشرکوں کی طرف سے معاندانہ رنگ میں ظاہر کیا جاسکتا تھا کہ یہ تمہارادعویٰ غلط ہے کہ ہمارے معبود ہدایت نہیں دے سکتے وہ بھی دلوں کے بھید جانتے ہیں اوروہ بھی ہدایت دیناچاہیں تودے
Page 57
سکتے ہیں.جیسا کہ اکثر مشرک اپنے معبودوں کو علم غیب کاجاننے والا ظاہر کرتے ہیں.(The Regved p :170 Editor Pandit Barhma Dutt Snatak M.A Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Bharat) حتٰی کہ بعض جاہل صوفی مسلمانوں میں سے بھی اس امر پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ من ذالک علم غیب رکھتے تھے.میں جب چھوٹاتھا.تُرکی ٹوپی کااستعما ل کیاکرتاتھا.ایک دفعہ ایک ایسے ہی شخص سے گفتگوکررہاتھا اورٹوپی کاپھُندنا میرے ہاتھ میں تھا.ا س نے کہاکہ رسول کریم صلعم کویہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں یہ پھُندنا ہے.بہرحال دوسری اقوام میں یہ خیا ل بڑی شدت سے پایا جاتا ہے.پس مشرک جواب میں یہ بات پیش کرسکتے تھے کہ انہیں بھی علم توہے مگر وہ اپنی مرضی سے الہام نہیں بھیجتے.کیونکہ انسان کوکسی بیرونی الہام کی ضرورت ہی نہیں.سواس کا جواب دیا کہ علم غیب خالق ہونے کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا.جوخالق ہے وہی اپنی مخلوق کے اندر کی طاقتوں اوراس کے فعلوں سے آگاہ ہو سکتا ہے.دوسراواقف نہیں ہوسکتا اوراگر واقف ہوتو ویساہی خالق وہ بھی ہوجائے.مگرجن کو تم معبود مانتے ہووہ توخالق نہیں.بلکہ سب کے سب خود مخلوق ہیں.خدا تعالیٰ کے سوا باقی ہستیوں کے علم غیب جاننے کا ردّ اس آیت سے کس لطیف پیرایہ میں خدا تعالیٰ کے سواسب باقی ہستیوں کے علم غیب جاننے کے دعویٰ کو رد کیا گیا ہے.مگر تعجب ہے کہ مسلمانوں میں اس تعلیم کی موجودگی میں ایک طبقہ ایساموجود ہے جویہ خیال کرتاہے کہ حضر ت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب بھی تھا اوروہ پرندے بھی پیدا کیاکرتے تھے.حالانکہ اللہ تعالیٰ اس جگہ صاف فرماتا ہے کہ جس قدروجودوں کی اللہ تعالیٰ کے سواپوجاکی جاتی ہے.ان میں سے ایک بھی کسی چیز کے پیداکرنے پر قادر نہیں.اورحضر ت عیسیٰ ؑ انہی وجودوں میں سے ہیں جن کی لاکھو ں کروڑوں انسان پوجاکرتے ہیں.اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ١ۚ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ١ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَؒ۰۰۲۲ وہ (سب)مردے ہیں نہ زندہ.اوروہ(یہ بھی )نہیں جانتے کہ کب (دوبارہ)اٹھائے جائیں گے.حلّ لُغَات.یَشْعُرُوْنَ.یَشْعُرُوْنَ شَعَرَ سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اورشَعَرَ بِہِ(شُعُوْرًا)کے معنے ہیں عَلِمَ بِہٖ.کسی چیز کو معلوم کیا شَعَرَلِکَذَا.فَطَنَ لَہٗ.اس کوسمجھا.عَقَلَہٗ.کسی چیز کوجانا.اَحَسَّ بِہٖ.اس کومحسوس کیا.(اقرب)پس مَایَشْعُرُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ انہیں معلوم نہیں.وہ
Page 58
محسوس نہیں کرتے.تفسیر.خالق ہونے کے علاوہ ہدایت دینے والے وجود کے لئے زندہ ہونابھی ضروری ہے.تاکہ جب کوئی خرابی ہو وہ اس کی اصلاح کرسکے.اس دلیل سے معبودان باطلہ کے ہدایت دینے کے قابل ہونے سے انکار کیااورفرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو سب فوت ہوچکے ہیں پھر وہ ہادی کس طرح ہوسکتے ہیں.اگر اس زمانہ میں خرابی پیداہو تووہ اسے کس طرح دورکریں گے.اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ کی آیت کے رو سے حضرت عیسیٰ ؑ کی وفات کا ثبوت تعجب ہے کہ مسلمانوں میں اس ارشاد کے خلاف بھی عقیدہ پیداہورہا ہے اور ایک کثیر جماعت حضرت عیسیٰؑ کو زندہ مان رہی ہے.حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس قدر جھوٹے معبود قرآن مجید کے زمانہ میں تھے وہ سب فوت ہوچکے تھے پس چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو معبود مانتے تھےاس الٰہی شہادت کے ماتحت وہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے فوت ہوچکے تھے.اوراگرانہیں زندہ تسلیم کیاجائے.توماننا پڑے گاکہ وہ نعوذ باللہ معبودانِ باطلہ میں سے نہ تھے بلکہ فی الواقعہ خدا تھے.نعوذ باللہ من ذالک.آیت لَا يَخْلُقُوْنَ اوراَيَّانَ يُبْعَثُوْنَمیں شرک کے رد میں چار زبردست دلائل ان دونوں آیات میں شرک کارد بھی نہایت زبردست دلائل سے کیا گیا ہے اوراس کے لئے چاردلائل دیئے ہیں.(۱)لَایَخْلُقُوْنَوہ پیدا نہیں کرتے.حالانکہ خداہونے کے لئے خالق ہوناضروری ہے.کیونکہ کامل وجود ہی معبود ہوسکتا ہے.(۲)وہ خود پیدا کئے گئے ہیں.یعنی ا ن میں احتیاج الی الغیر پائی جاتی ہے اورمحتاج الی الغیر ناقص ہوتاہے معبود نہیں ہوسکتا.(۳)وہ مردہ ہیں.زندہ نہیں.یعنی اس زمانہ میں وہ بے نفع اوربے ضرر ہیں.اورخداوہی ہوسکتا ہے جو ہمیشہ نفع اورضرر کی طاقت رکھتاہو.(۴)انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ و ہ کب اٹھائے جائیںگے.گویاان کاانجا م بھی دوسرے کے ہاتھ میں ہے.اس آخری دلیل کے متعلق کہاجاسکتا ہے کہ اس کاکیاثبوت ہے کہ انہیں علم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے سو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ پوجاجانے والا وجود حضرت مسیح کاہے.وہ یوم البعث کے متعلق خود کہتے ہیںکہ.
Page 59
حضرت مسیح ؑ کا یوم البعث کے متعلق عدم علم کا اقرار ’’لیکن اس دن یااس گھڑ ی کی بابت کوئی نہیں جانتا.نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا.مگر باپ.خبردار!جاگتےاوردعامانگتے رہو.کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا‘‘.(مرقس با ب۱۳ آیت ۳۲،۳۳) پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اقرار پر باقی خدامانے جانے والے انسانوں کے متعلق بھی قیاس کیا جاسکتا ہے.اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ١ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ تمہارامعبود ایک ہی معبود ہے اورجولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے.ان کے دل (حق سے )ناآشناہیں.قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ۰۰۲۳ اوروہ تکبر سے کام لے رہے ہیں.حلّ لُغَات.قُلُوْبُھُمْ مُنْکِرَۃٌ.مُنْکِرَۃٌ اَنْکَرَ سے اسم فاعل مؤنث کاصیغہ ہے اوراس کے معنے جاہل اورناواقف کے ہیں.پس قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ کے معنے یہ ہوئے کہ ان کے دل جہالت میں مبتلاہوگئے.مزید تشریح کے لئے دیکھو حجرآیت نمبر۶۳.مُنْکَرُوْنَ اَنْکَرَ سے اسم مفعول مُنْکَرٌ بنتاہے اورمُنْکَرُوْنَ اس کی جمع ہے.اَنْکَرَہُ کے معنے ہیں جَہِلَہٗ اس کونہ پہچانا.اَنْکَرَ حَقَّہٗ کے معنی ہیں جَحَدَہٗ اس کے حق کاجان بوجھ کر انکار کردیا.اَنْکَرَ عَلَیْہِ فِعْلَہُ: عَابَہُ وَنَھَاہُ اس کے فعل کومعیوب قرار دیا اوراس سے اُسے روکا.اَلْمُنْکَر کے معنی ہیں مَالَیْسَ فِیْہِ رِضَی اللّٰہِ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ وَالْمَعْرُوْفُ ضِدُّہٗ.منکر وہ فعل یاقول ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اورلفظ معروف (پسندیدہ) اس کے مخالف معنے اداکرنے کے لئے بولاجاتاہے (اقرب) تفسیر.قرآن مجید کے منکروں سے خطاب کرنے کے دو طریق یہ جو فرمایاکہ تمہارا خدا ایک ہی خداہےیہ خالی دعویٰ نہیں.قرآن کریم جب منکروں سے خطاب کر تا ہے توصرف دعویٰ پیش نہیں کرتا.کیونکہ ان پر خالی دعویٰ کااثر نہیں ہوسکتا.بلکہ وہ ایسے موقعہ پر دومیں سے ایک طریق اختیار کرتا ہے.
Page 60
قرآن مجید کا دعویٰ کے بعد دلائل بیان کرنا یا واقعات کے بعد ان کے طبعی نتائج بیان کرنا یاتودعویٰ بیان کرنے کے بعد ہی اس کے دلائل دیتاہے یادلائل بیان کرکے بعد میں اس کانتیجہ پیش کرتاہے اوریہی دوطبعی طریق ہیں جن سے انسانی دماغ تسلی پاتاہے اوردونوں اپنے اپنے رنگ میں نہایت موثر ہیں.بعض دفعہ دعویٰ بیان کرکے بعد میں دلائل دینا مفید ہوتا ہے اور بعض دفعہ واقعات بیا ن کرکے بعد میں ان کا طبعی نتیجہ بیان کر نا مفید ہوتاہے.اس جگہ دوسراطریق اختیار کیا ہے اورپہلی آیات کاعقلی نتیجہ پیش کیا ہے.پہلی آیات میں دومضمون بیان ہوئے ہیں.ایک تویہ کہ سب کائنات ایک ہی رشتہ میں پروئی ہوئی ہے اورایک چیز کادوسری پرانحصار ہے.انسان کی پیدائش اصل ہے.اس کی غذااول حیوانی ہے.حیوان درختوں و غیر ہ سے غذاحاصل کرتے ہیں.آگے وہ درخت اوربوٹیاں آسمانی پانی سے پلتے ہیں اوروہ پانی انسان کے پینے کے کام بھی آتا ہے.پھر اُسی پانی سے نباتا ت اُگتی ہیں جوانسان کی غذائیں بنتی ہیں.یہ سب اشیاء رات، دن، سورج، چاند اورستاروں کی تاثیر ات سے نشوونماپاتی ہیں.دوسری طرف ان کے قیام کا ذریعہ سمندر ہے جس میں پانی کاذخیرہ رہتا ہے.اور اس سے پانی چھن کر پھر انسانوں کو ملتاہے.اوراس سمندر کو اپنے حال پر رکھنے کے لئے پہاڑ ہیں جوپانی جمع رکھتے ہیں.وہاں سے دریائوں کے ذریعہ سے پانی بہتاہے جوخاص راستوںپر چل کر سمندرمیں آکر گرجاتا ہے اورسطح زمین پر پھیل نہیں جاتاکہ زمین انسانوں کی رہائش کے قابل نہ رہے.ان سب امورسے ایک واضح نتیجہ نکلتا ہے اوروہ یہ کہ دنیا کی ہرچیز ایک دوسرے سے وابستہ ہے.اوردنیامتفرق چیزوں کامجموعہ نہیں.بلکہ اس کااختلاف ایسا ہی ہے جیسے ایک زنجیر کی کڑیا ں.اگر ایک کڑی نکال دی جائے تو زنجیر ،زنجیر نہیں رہتی.اسی طرح کائنا ت میں سے ایک چیز کو نکال دو ساری دنیا تباہ ہوجائے گی.سمندر خشک کردو پانی ختم ہوجائے گا.دریا خشک کردو سمندر خشک ہوجائے گا.اس نشیب کو جو دریائوں کے لئے راستہ بناتا ہے دورکردو.سب دنیا پر پانی پھیل جائے گا اور زمین رہائش کے قابل نہ رہے گی.پہاڑ مٹادو زمین پر زلزلے آئیں گے اورانسان ہلاک ہوجائے گا.دریائوں کے لئے پانی کاذخیرہ باقی نہ رہے گااوروہ سارا پانی یکدم سمندر میں جاگرائیں گے.اگر ایک طرف دنیا سیلاب کی نظر ہوگی تودوسری طرف سال بھر تک پانی کے مہیا رہنے کی صورت مفقود ہوجائے گی.چاند ستاروںکو مٹادو توجو ان کی وجہ سے پیدائش عالم پر اثر ہے و ہ جاتارہے گااورزمین اپنی حالت پر نہ رہے گی.سورج کو الگ کردو یہ بادلوں کا سلسلہ جاتارہے گا اور لوگ پانی کو ترس جائیں گے اورسبزیوں کاپکنا بند ہوجائے گا.اورانسان کی صحت خراب ہو جائے گی.اوراس کی حیوانی غذاکے پیدا ہونے کا بھی امکان نہ رہے گا.
Page 61
کائنات کا نظام خدا تعالیٰ کے واحد ہونے کی دلیل ہے غرض یہ سب کائنات مل کرانسان کی خدمت کررہی ہے.اوراس کا ہر حصہ دوسرے حصے کے قیام کاذریعہ ہے.جب یہ حال ہے توپھردوخدا کاعقیدہ کس طرح درست ہو سکتا ہے.اگر دنیا کو کئی خدائوں نے پیدا کیا ہے.تووہ کون ساحصہ ہے جس کے بارہ میں کہاجاسکتاہے کہ وہ دوسرے سے آزاد ہے کہ سمجھا جاسکے کہ اُسے کسی اورنے پیدا کیا ہوگا.اوراگر ساری کائنات ایک زنجیر کی کڑیوں پر مشتمل ہے توا س کا بنانے والا ایک ہی خداتسلیم کرنا پڑے گا.سوائے اس کےکہ یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ میں سب کائنات بنانے کی قدرت نہ تھی.اس لئے کئی خدائوں نے مل کر کا م تقسیم کرلیا اورپہلے سے تجو یز کردہ نقشہ کے مطابق ہراک نے اپنا اپنا حصہ پور اکیا.لیکن یہ عقید ہ مشرکوں کابھی نہیں اورہے بھی خلاف عقل.کیونکہ ناقص وجود خدانہیں ہوسکتے.پس اس دلیل کی موجود گی میںایک ہی نتیجہ نکلتاہے کہ اِلٰھُکُمْ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ تمہارا خد اوہی ہے جو ایک ہے.دوسرامضمون پہلی آیات میں یہ بتایاگیاتھا کہ وہ سب وجود جن کو خداکہاجاتا ہے فوت ہوچکے ہیں.پس جب وہ فوت ہوچکے ہیں توپھر بھی ایک ہی خداباقی رہ جاتاہے جوموت سے بالا ہے.پس اِلٰھُکُمْ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ میں پہلے مضامین کانتیجہ بیان کیاگیا ہے اورکوئی بے دلیل دعویٰ بیان نہیں کیاگیا.بعث بعد الموت کے انکار کے دو نتائج اس کے بعد فرماتا ہے.فَالَّذِیْنَ لَایُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ قُلُوْبُھُمْ مُّنْکِرَۃٌ وَّھُمْ مُّسْتَکْبِرُوْنَ اس جگہ فا ء، واو کے معنوں میں ہے اورفاء ،واو کے معنوں میں عربی زبان میں مستعمل ہوتی ہے.(اقرب) اورترجمہ یہ ہے کہ ’’اورجولوگ آخرۃ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اوروہ تکبر سے کام لیتے ہیں‘‘اس فقرہ میں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ اگرخدا تعالیٰ کا ایک ہونا ایسا بدیہی امر ہے تولوگ اس کے ایک ہونے کا انکار کیوںکرتے ہیں.اوروہ جواب یہ ہے کہ یہ انکار کسی دلیل پر مبنی نہیں.بلکہ باوجود ان دلائل کے شرک میں مبتلاہونا اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ بعث بعد الموت کے منکر ہیں.اوراس انکا ر کی وجہ سے ان کے اندر سنجیدگی باقی نہیں رہی.کیونکہ جب یہ اپنے افعال کو بغیر نتیجہ سمجھتے ہیں توانہیں ان کے اچھا براہونے کے متعلق خاص فکر پیدا نہیں ہوتی.اورضداورتعصب میں کوئی حرج نہیں دیکھتے.کیونکہ ان کے خیال میں گرفت توکوئی ہونی نہیں.اس لئے آہستہ آہستہ ان کے دل جاہل اورغبی ہوگئے ہیں.اوروہ مادہ سمجھ اورہدایت کا ان میں باقی نہیں رہاجو اس وقت انسان میں پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ یہ محسوس کر تاہے کہ میرے اعمال کا کوئی اہم نتیجہ نکلنے والا ہے.غرض آخرت کے انکار کی وجہ سے لاابالی پن اورسنجیدگی کافقدا ن ان میں پیداہوگیا ہے اوردل علم سے محروم رہ گئے ہیں.اور اس وجہ سے بدیہی اوریقینی باتوں کاانکار بھی دلیر ی سے کردیتے ہیں.اورغور کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے.غرض اس جگہ مُّنْكِرَةٌ کے
Page 62
معنے انکار کرنے والے کے نہیں بلکہ جاہل اورناواقف کے ہیں.اوریہ بتایاہے کہ بعث بعد الموت پر ایمان نہ ہونے کے سبب سے چونکہ سنجید گی سے غور کرنے کا احساس نہیں اس لئے اس عادت کی وجہ سے دلوں سے سمجھ کامادہ جاتارہا ہے اوران کو حس ہی نہیں ہوتی کہ ہماراایک عقیدہ دوسرے عقید ہ کے خلاف ہے.دوسرا نتیجہ بعث بعد الموت کے انکا ر کا یہ بتایاکہ ان میں تکبر پیداہوگیا ہے کیونکہ جو شخص جزاسزاکا مومن نہ ہو و ہ نڈر ہو جاتا ہے اورجو نڈر ہوجائے وہ سچائی کااقرار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا.قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ کے الفاظ سے دو قسم کے مشرکوں کا ذکر غرض قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ اور هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَکے الفاظ سے درحقیقت دو قسم کے مشرکوں کا ذکر فرمایا ہے.ایک وہ ہیں جن سے سنجیدگی سے غور کرنے کامادہ جاتا رہا ہے اورجہالت میں مبتلاہوگئے ہیں.پس بوجہ دل کے بیمار ہوجانے کے و ہ سچائی کے سمجھنے سے قاصر رہ گئے ہیں.اور دوسرے وہ لوگ جو دلائل سن کر ایک خداکے عقیدہ کو دل میں توصحیح سمجھتے ہیں لیکن تکبر اورضد کی وجہ سے اس کا اقرار نہیں کرتے.کیونکہ جزاءسزاکے انکار کی وجہ سے و ہ بے خوف ہیں.اورسچائی کے انکار میں کوئی نقصان نہیں دیکھتے.لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ١ؕ اِنَّهٗ لَا یہ یقینی بات ہے کہ جوکچھ وہ پوشیدہ (طورپر)کرتے ہیں (اسے بھی )اورجوکچھ وہ ظاہر (طورپر )کرتے ہیں (اسے يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ۰۰۲۴ بھی )اللہ (تعالیٰ)جانتاہے.وہ تکبر کرنے والوں کو ہرگزپسند نہیں کرتا.حلّ لُغَات.لَاجَرَمَ کی تشریح کے لئے دیکھو ہود آیت ۲۳.جَرَمَ یَجْرِمُ جَرْمًا قَطَعَ کاٹ دیا.لَاجَرَمَ قَالَ اَلْفَرَّاءُ ھِیَ کَلِمَۃٌ کَانَتْ فِی الْاَصْلِ بِمَنْزِلَۃِ لَابُدَّ وَلَا مَحَالَۃ فَـجَـرَتْ عَلٰی ذٰلِکَ وَکَثُرَتْ حَتّٰی تَحَوَّلَتْ اِلٰی مَعْنَی الْقَسَمِ.وَصَارَتْ بِمَنْزِلَۃِ حَقًّا وَھُوَمَأْخُوْذٌ مِنَ الْقَطْعِ.فرّاء کا قول ہے کہ لَاجَرَمَ پہلے لَا بُدَّ یعنی ضرور کے معنی میں استعمال ہوا کرتا تھا پھر کثرت استعمال سے ہوتے ہوتے اس کے معنی قسم کے بن گئے اور حقاً یعنی یقیناً کے معنی دینے لگا ورنہ اس کے اصل معنی یہی ہیں کہ اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا یعنی یہ اٹل بات ہے.(اقرب)
Page 63
تفسیر.انکار بعث سے جہالت میں پڑنے والوں کی سزا توحید کا تکبر سے انکار کرنے والوں سے کم ہوگی فرمایا جس طرح اوپر بیان کئے گئے دلائل سے ایک خدا کا ثبوت ملتا ہے اس کے عالم الغیب ہونے کاثبوت بھی ملتاہے.پس اللہ تعالیٰ جو ان کے ظاہرو باطن کو جانتاہےوہ ان کو ان کے اعمال کی ضرور سزادے گا.ہاں وہ یہ فرق ضرورکرے گاکہ جو لوگ انکار بعث کی وجہ سے جہالت میں مبتلاہوگئے ان کی سز اان لوگوںسے کم ہوگی جو توحید کو سمجھتے توہیں.مگر تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں.اِنَّہٗ لَایُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِیْنَ کے الفاظ سے اسی طرف اشار ہ کیا گیا ہے کہ جولوگ جان بوجھ کر انکارکرتے ہیں و ہ زیاد ہ سزاکے مستحق ہوں گے.وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّا ذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ١ۙ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ اورجب ان سے کہاجاتاہے (کہ)وہ (کلام )جوتمہارے رب نے اتار اہے کیا(ہی شاندار)ہے.تووہ کہتے ہیں الْاَوَّلِيْنَۙ۰۰۲۵ (کہ) یہ (خدا تعالیٰ کاکلام نہیں بلکہ)پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں.حلّ لُغَات.اَسَاطِیْرُ.اَسَاطِیْرُ سَطَرَ سے بناہے.اورسَطَرَ الْکَاتِبُ کے معنے ہیں کَتَبَ.اس نے لکھا.اورسَطَرَالرَّجُلَ کے معنے ہیں صَرَعَہٗ.کسی کو کشتی میں گرالیا.سَطَرہٗ بِالسَّیْفِ:قَطَعَہٗ بِہٖ.اس کو تلوار سے کاٹ ڈالا.اَلْاِسْطَارُ وَالْاُسْطَارُ وَالْاُسْطُوْرُ وَالْاُسْطِیْرُ:مَایُسْطَرُ اَیْ یُکْتَبُ وَتُسْتَعْمَلُ فی الْحَدِیْثِ لَا نِظَامَ لَہٗ.یعنی اِسْطَارٌاور اُسْطَارٌ اُسْطُورٌاور اُسْطِیْرٌ کے معنے لکھی ہوئی چیز کے ہیں اور ایسی باتوں کو بھی کہتے ہیں جن میں کوئی نظام نہ ہو.وَالْـحِکَایَاتُ اورقصے کہانیوں کو بھی کہتے ہیں.اس کی جمع اَسَاطِیْر آتی ہے (اقرب) پس اَسَاطِیْرُالْاَوَّلِیْنَ کے معنے ہوں گے پہلے لوگوں کی تحریری حکایتیں یاکہانیا ں یابے جوڑ باتیں.تفسیر.منکرین توحید اور بعث بعد الموت کا قرآنی دلائل کے اثر کو مٹانے کا غلط طریق اس آیت سے پھر اصل مضمون کی طرف رجوع فرمایا اوربتایا کہ یہ منکرین توحید اوربعث بعد الموت جب ان دلائل کو سنتے ہیں تو بجائے غورکرنے کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں.یہ توپہلے لوگوں کی باتوں کونقل کردیاگیا ہے.اُسْطُوْرٌجس کی جمع اَسَاطِیْرُ ہے اس کے معنے کہانی کے بھی ہوتے ہیں اورکتاب کے بھی.اورگودونوں معنے اس آیت میں چسپاں ہوسکتے ہیں.مگر سیاق کو مدنظر رکھتے ہوئے کتاب کے معنے زیادہ چسپا ں ہوتے ہیں کیونکہ اس سورۃ
Page 64
میں نبیوں کے واقعات بیان نہیں ہوئے بلکہ بعض دلائل بیان ہوئے ہیں.پس سیاق کے لحاظ سے یہاں یہی معنے زیادہ چسپاں ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جودلائل کو سنتے ہیں توڈرتے ہیں کہ لوگوں پر اثر نہ ہوجائے اوراثر کو مٹانے کے لئے تخفیف کے لئے کہتے ہیں کہ اجی یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے کئی لوگ یہ باتیں لکھ چکے ہیں ہم ا ن باتوں سے خوب واقف ہیں.گویا اس طرح وہ اپنے اتباع پر یہ اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ خدائی کلام نہیں صرف پہلے لوگوں کی باتوں کو نقل کرکے یہ شخص بیان کررہاہے اورہم ان باتوںکو پہلے سے ہی جانتے ہیں اوران کی غلطی سے واقف ہیں.الٰہی دلائل کو مخالفین کا پہلوں کی نقل شدہ باتیں کہنا ہمیشہ کا وطیرہ ہے یہ حربہ حق کے خلاف ہمیشہ سے استعمال ہوتاچلا آتاہے.جب ائمۃ الکفر دیکھیں کہ دلائل زبردست ہیں اوران کا جواب دینا مشکل ہے.توہمیشہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے ہیں کہ اجی بس کرو یہ بھی کوئی دلائل ہیں.ہمیشہ سے لوگ یہ بات کہتے چلے آئے ہیں.تم نے ان سے نقل کرکے آگے لوگوں کو سنادی ہیں اوران کے جاہل اتبا ع دلیل کی خوبی سے غافل ہوجاتے ہیں اوراسی پر خوش ہوجاتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں اس لئے خدائی کلام نہیں ہوسکتا.گویاکہ خدائی کلام وہ ہوتاہے جس میں نئی نئی باتیں بیان کی جائیں.حالانکہ خدائی کلام کی غر ض توگمشدہ صداقتوں کو قائم کرناہوتا ہے.گواس میں زمانہ کی ضرورت کے مطابق نئے علوم بھی ہوتے ہیں.مگر اصولی باتیں سب نبیوں کی ایک ہی ہوتی ہیں.اِن اصولی باتوںکو چھوڑ کر جو نئی بات کہے گاو ہ توجھوٹ ہی بولے گا.لِيَحْمِلُوْۤا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ١ۙ وَ مِنْ اَوْزَارِ جس (قول) کے نتیجہ میں وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ (بھی )پورے (پورے)اٹھائیں گے اوران کے بوجھ بھی الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ١ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَؒ۰۰۲۶ جن جاہلوںکو وہ گمراہ کررہے ہیں.سنو!جو بوجھ وہ اٹھارہے ہیں وہ بہت (ہی )بُراہے.حلّ لُغَات.اَوْزَارٌ.اَوْزَارٌ وِزْرٌکی جمع ہے اوروِزْرٌ وَزَرَ کامصدر ہے.وَزَرَہٗ کے معنے ہیں حَمَلَہٗ.اس نے اس کو اٹھایا.وَفِی اللِّسَانِ حَمَلَ مَایُثْقِلُ ظَھْرَہٗ مِنَ الْاَشْیَاءِ الْمُثْقِلَۃِ.اورلسان میں لکھا ہے کہ وِزْرٌ کالفظ ایسے بوجھ کے اٹھانے کے لئے بولتے ہیں جس کااٹھانا مشکل ہو.نیزاَلْوِزْرُ کے معنے ہیں اَلْاِثْمُ.گناہ.اَلثِّقَلُ.بوجھ.اَلسِّلَاحُ لثِقَلِہِ عَلٰی حَامِلِہِ.ہتھیار کیونکہ وہ بھی اٹھانے والے پر بوجھل ہوتے
Page 65
ہیں.اَلْحِمْلُ الثَّقِیْلُ.بھاری بوجھ.اس کی جمع اَوْزَارٌآتی ہے (اقرب) تفسیر.فرمایا اس قسم کی باتوں سے یہ عوام کو دھوکاتودے لیتے ہیں.لیکن اپنی عاقبت کواوربھی خراب کرلیتے ہیں.آخر جزاء کے دن ان کے اپنے بداعمال کے علاو ہ اس جر م کی سزابھی ان کو ملے گی کہ فریب اوردھوکے سے جاہل عوام کوگمراہ کرتے رہے.لِيَحْمِلُوْۤا میں لام.لام عاقبت ہے جس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات کے نتیجہ میں یہ بات پیداہوئی ہے.اورمعنے یہ ہیں کہ اس دھوکہ دہی کانتیجہ یہ نکلے گاکہ یہ اپنے گناہوں کی سزابھی پائیں گے اوران کے اعمال کی بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا.بِغَيْرِ عِلْمٍ يُضِلُّوْنَهُمْ کی ضمیر مفعول کا حال ہے بِغَيْرِ عِلْمٍ.يُضِلُّوْنَهُمْ کی ضمیر مفعول کاحال ہے اور یہ مراد نہیں کہ گمراہ کرنے والے بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں.کیونکہ ان آیات میں توذکر ہی یہ ہے کہ یہ لوگ شرارت سے گمراہ کر رہے ہیں.بلکہ معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اپنے اتباع کو جوکوئی علم نہیں رکھتے باتیں بناکر گمراہ کردیتے ہیں.کَامِلَۃً کے لفظ کے دو معنے کَامِلَۃً.اس لفظ کے دوطرح معنے کئے جاسکتے ہیں (۱)اگرتواسے يَوْمَ الْقِيٰمَةِ کا متعلق سمجھاجائے تومعنے یہ ہوں گےکہ کچھ سزاتوانہیں یہاں دنیا میں ملے گی لیکن پوری سزاان کو قیامت میں ملے گی (۲)اگر اسے لِيَحْمِلُوْۤا کامتعلق سمجھاجائے تواس کے معنے ہوں گے کہ یہ اپنے سارے کے سارے بوجھ اٹھائیں گے اورکوئی بوجھ کم نہ ہوگا.یعنی مومن تواستغفار کرتا رہتا ہےاس لئے اس کے بوجھ کم ہوتے رہتے ہیں اورگناہ معاف ہوتے رہتے ہیں.مگر یہ متکبر ہیں اس لئے ان کے سب گناہ باقی رہ جائیں گے اورسب کی سزا ان کو ملے گی.قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے (بھی اپنے اپنے زمانہ کے انبیاء کے خلاف)تدبیریں کی تھیں جس کے نتیجہ میں الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ اَتٰىهُمُ اللہ (تعالیٰ)ان کی عمارتوںکے پاس ان کی بنیادوں کی طرف سے آیا.جس پر چھت ان کے اوپر کی طرف سے ان پر
Page 66
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ۰۰۲۷ آن گری اور(اس کایہ )عذاب اُن پر ایسی طرف سے آیاکہ وہ (کچھ)نہیں سمجھتے تھے (کہ کہاں سے آگیا ).حلّ لُغَات.مَکَرَ کسی کو اس کے قصد سے کسی تدبیر کے ذریعہ سے پھیرنے کانام مکر ہے اوریہ اچھابھی ہوتاہے اوربُرابھی (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھیں رعد آیت نمبر ۴۳.مَکَرَہٗ کے معنے ہیں خَدَعَہُ.اس کو دھوکا دیا.اللہُ فُلَانًا: جَازَاہُ عَلی الْمَکْرِ.جب اللہ تعالیٰ کے لئے مَکَرَ کا لفظ آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکر کا بدلہ دیا.قِیْلَ الْمَکْرُ صَرْفُ الْاِنْسَانِ عَنْ مَقْصَدِہِ بِحیْلَۃٍ.بعض نے کہا کہ کسی کو اس کے قصد سے کسی حیلہ کے ذریعہ سے پھیرنے کا نام مکر ہے.وَھُوَ نَوْعَانِ مَحْمُوْدٌ یُقْصَدُ فِیْہِ الْخَیْرُ وَمَذْمُوْمٌ یُقْصَدُ فِیْہِ الشرُّ.اور مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی.(اقرب) اَتَی اللہُ بُنْیَانَھُمْ: اَتٰی کی تشریح کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر ۴۲.اَ تَاہُ کے معنے ہیں جَاءَ ہٗ.اس کے پاس آیا.وَالْاَمْرَ: فَعَلَہٗ.اور جب اَتٰی کا مفعول اَلْاَمْرَ ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں کام کو کیا.اَتٰی الْمَکَانَ : حَضَرَہٗ.کسی جگہ گیا.اَتٰی عَلَی الشَّیءِ: اَنْفَدَہٗ.اس کو ختم کیا.وَبَلَغَ اٰخِرَہٗ اور اس کے انتہاء تک پہنچا.اَتٰی عَلَیْہِ الدَّھْرَ.اَھْلَکَہٗ.زمانہ نے اسے ہلاک کیا.(اقرب) القواعدُ.اَلْقَوَاعِدُاس کا مفرد الْقَاعِدَ ۃُ ہے اور قَوَاعِدُ الْبَیْتِ کے معنے ہیں اَسَاسُہٗ.گھر کی بنیادیں.(اقرب) خَرَّکے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر۱۰۱.خَرُّوْا خَرَّ ماضی سے جمع غائب کا صیغہ ہے.جس کے معنے ہیں سَقَطَ.سُقُوْطًا یُسْمَعُ مِنْہُ خَرِیْرٌ.ایسے طور پر گرنا کہ اس سے آواز سنائی دے.وَالْخَرِیْرُ یُقَالُ لِصَوْتِ الْمَاءِ وَالرِّیْحِ وَغَیْرِ ذٰلِکَ مِمَّا یَسْقُطُ مِنْ عُلُوٍّ.(مفردات) اور خریر اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے اوپر سے گرنے یا ہوا اور پانی کے چلنے سے پیدا ہو.تفسیر.فرمایا اس طرح اشتعال دلاکر اوردھوکا دے کر لوگوں کو نبیوں کی تعلیم سے ناواقف رکھنا کو ئی نئی بات نہیں.بلکہ پہلے انبیاء کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوتاچلا آیا ہے.مگر ان تدبیروں سے کبھی بھی نبیوں کے دشمن کامیاب نہیں ہوئے.یہ تدابیر آخر اُلٹ کر انہی پر پڑتی رہی ہیں.آنحضرت ؐ پر پہلوں کی نقل کرنے کے اعتراض کا جواب یہ طریق کلام کیسالطیف ہے.دشمنان اسلام
Page 67
کایہ اعتراض پہلے بیان ہواہے کہ یہ مدعی کوئی نئی تعلیم تونہیں لایا.پہلے لوگوں کی باتوں کو نقل کررہا ہے.اس آیت میں ان کا اعتراض انہی کے متعلق دُہرادیا اورفرمایاکہ یہ سچ ہے کہ یہ نبی بہت سی باتیں وہ بیان کرتا ہے جوپہلے نبیوں نے بھی کہی ہیں.اور تم ان کو نقل کہتے ہو.مگر اپنا حال نہیں دیکھتے کہ تم بھی پہلے نبیوں کے دشمنوں کی نقل کررہے ہو اورویسی ہی شرارتیں کررہے ہو جیسی کہ پہلے نبیوں کے دشمن کیاکرتے تھے.اگر اس نبی کاکلام پہلے لوگوں کی نقل ہے تووہ اچھی نقل ہے.مگر تمہار ے کام بھی نقل ہیں اوربُرے لوگوں کی نقل ہیں.نبی کی نقل اور کفار کی نقل میں فرق پس نقل کہہ کر بھی توتم اعتراض سے نہیں بچ سکتے.کیونکہ یہ توان کی نقل کرتاہے جوآخر کامیاب ہوئے اور تم ان کی نقل کررہے ہو جو آخر ہلاک ہوئے.پس اگر دونوں طرف سے نقل ہورہی ہے توبھی تم ہی خسارہ میں رہتے ہو.کیونکہ تباہ ہونے والوں کی نقل کررہے ہو.چنانچہ ان لوگوں کاحال بتاتا ہے جن کی کفار نقل کررہے تھے.اورفرماتا ہے کہ تمہاری ہی طرح پہلے انبیاء کے دشمن بھی لوگوں کو نبیوں کے خلاف یہ کہہ کربھڑکایاکرتے تھے کہ یہ نقال ہیں.مگر کیا اس اعتراض یا ایسے ہی اوراعتراضوں سے وہ نبیوں کی تعلیم کے پھیلنے میں کوئی کامیاب روک پیداکرسکے.کیااس طرح وہ نبیوں کے تباہ کرنے میں کامیاب ہوسکے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ خود ہی تباہ ہوئے.ائمۃ الکفر کو لوگوں کو دھوکہ دے کر نبیوں کی تعلیم سے ناواقف رکھنے کی سزا پھر ان کے عذاب کی نوعیت بتائی کہ تباہی بھی معمولی تباہی نہ تھی بلکہ اَتَیْ اللّٰہُ بُنْیَانَھُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَیْھِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِہِمْ.یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اس طرح عذاب نازل کیا کہ ان کی خود ساختہ عمارتوں کی بنیادوں کواُکھاڑ پھینکا اوردیواروں کے ساتھ چھتیں بھی گر گئیں.یعنی نہ توابع رہے نہ افسر سب ہی ہلاک ہوئے اور وہی دیواریںیعنی توابع جن پرانہیں ناز تھا اس طرح اوندھے منہ گرے کہ اپنے ساتھ اپنے سرداروں کو بھی لے گرے.پس عوام الناس پر جو تم کو اثر حاصل ہے اس پرمغرور نہ ہوکہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آتاہے تویہ حکومت دھری رہ جاتی ہے اورخدا تعالیٰ کفار کے سارے نظام کو تباہ کردیتا ہے اورافسر اورماتحت سب ہی گرتے ہیں.بلکہ توابع ہی سرداروں کی تباہی اورہلاکت کاموجب ہوجاتے ہیں.پھر بتایاکہ یہ عذاب ہمیشہ غیر معمولی طریق سے آتے رہے ہیں.حتٰی کہ ائمہء کفرکو علم بھی نہ ہوتاتھا کہ عذا ب آرہاہے اورعذاب آجاتاتھا.اورایسی راہوں سے آتاتھا.جن کا انہیں وہم اورگمان تک نہ ہوتاتھا.اللہ کے منکروں کے پاس آنے سے مراد عذاب کا آنا ہوتا ہے اَتَی اللہُ.اللہ تعالیٰ کے منکروں کے
Page 68
پاس آنے کے معنے ہمیشہ عذاب کے ہوتے ہیں.بہائیوں کا اَتَی اللہُ سے غلط استدلال اور اس کا جواب بہائیوں نے اسی قسم کی آیات پیش کرکے کہاہے کہ دیکھو قرآن کریم میں لکھاہے کہ خداخود آئے گا.اس سے مراد بہاء اللہ کاظہو رہے.حالانکہ یہ معنے قرآنی محاورہ کے سراسرخلاف ہیں.جیساکہ یہ آیت صاف ظاہرکررہی ہے.ہاں اگربہاء اللہ کو اس زمانہ کے لوگوں کے لئے ایک عذاب سمجھاجائے توان کو بھی اللہ کی آمد کا عذابی ظہور ماننے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ دین سے غافلوں کو اورزیادہ غفلت کے سامان پیداکرکے عذاب دیاکر تاہے.اس آیت میں اہل مکہ کو ان کی عمارت کے انہدام کا انتباہ اس آیت میں اہل مکہ کو گذشتہ واقعات کاحوالہ دے کر ہوشیار کیا گیا ہے کہ اب تمہارانظام کھوکھلاہوچکاہے.اب تووہ خود ہی گرنے کو تیار کھڑاہے.تم نے محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو کیا تباہ کرنا ہے تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہاری عمارت دیوار وں اور چھتوں سمیت زمین پرآرہے گی.تاریخ دان جانتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے آخری دن تک کفار غالب معلوم ہوتے تھے لیکن یکدم ان کی عمارت پیوند خاک ہوگئی.ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَ يَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ پھر وہ قیامت کے دن (دوبارہ )انہیں رسواکرے گااورکہےگا(کہ اب )کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی وجہ سے الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ١ؕ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا تم (میرے انبیاء سے)دشمنی (اورمخالفت )رکھتے تھے.(اور)جنہیں علم دیاگیاہوگا وہ (اس وقت)کہیں گے کہ الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَۙ۰۰۲۸ آج کافروں پر یقیناًرسوائی اورمصیبت(آنے والی)ہے.حل لغات.ثُمَّ:حرف عطف ہے جوترتیب اورتراخی کے لئے آتاہے.یعنی یہ ظاہرکرتا ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے بعد ترتیباًاور کچھ دیر بعد واقع ہواہے (اردوزبان میں اس مفہوم کو اداکرنے کے لئے پھر ،تب،بعد ازاں کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ) اوربعض اوقات ثُمَّ کے آخر میں تاء بھی لے آتے ہیں.جیسے
Page 69
کہ اس شعر میں اِسے لایاگیا ہے.وَلَقَدْ اَمُرُّعَلَی اللَّئِیْمِ یَسُبُّنِیْ فَمضَیْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَایَعْنِیْنِیْ (اقرب) یَوْمٌ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۴.اَیَّامٌ یَوْمٌ کی جمع ہے.اَلْیَوْمُ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلٰی غُرُوْبِ الشَّمْسِ.دن کا وقت.اَلْوَقْتُ مُطْلَقًا.مطلق وقت جو بھی اور جتنا بھی ہو (اقرب) یُخْزِیْھِمْ:یُخْزِیْ اَخْزٰی سے مضارع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اوراَخْزَاہُ کے معنے ہیں اَوْقَعَہٗ فِی الْخِزْیِ اَوِلْخِزَایَۃِ وَاَھَانَہٗ.اس کو کسی ایسی بات میں پھنسایاجس سے اُسے ندامت ہواوراس طرح سے اُسے ذلیل کیا.اَخَزَی اللہُ فُلَانًا کے معنے ہیں فَضَحَہٗ.اللہ تعالیٰ نے اس کے عیوب کوظاہر کردیا.اوراس طرح وہ رسواہوگیا (اقرب) پس یُخْزِیْھِمْ کے معنے ہوں گے ان کے عیوب کو ظاہرکرکے اللہ تعالیٰ انہیں رسواکرے گا.تُشَاقُّوْنَ:تُشَاقُّوْنَ شَاقَّ سے مضارع جمع مذکر مخاطب کاصیغہ ہے اور شَاقَّہٗ کے معنے ہیں خَالَفَہٗ.اس سے ناموافقت کی.عَادَاہٗ.اس سے دشمنی کی (اقرب)پس کُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ کے معنے ہوں گے (۱)تم مخالفت کرتے تھے (۲)تم دشمنی کرتے تھے.اَلْخِزْیُکے اصل معنے ایسی ذات کے ہیں جولوگوں کے سامنے شرمندگی کا موجب ہو.مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۹۹.اَلْخِزْیُ الْھُوَانُ ذلت.ذلیل و حقیر ہونا.اَلْعِقَابُ.سزا.اَلْبُعْدُ دوری.اَلنَّدَامَۃُ شرمندگی، پچتانا.واَصْلُ الْخِزْیِ ذِلٌّ یُسْتَحْیٰ مِنْہُ اس کے اصل معنی ایسی ذلت کے ہیں جو لوگوں کے سامنے شرمندگی کا موجب ہو.(اقرب) تفسیر.آنحضرت ؐ کے مخالفین پر رسوائی اور ہلاکت کے دونوں عذاب بعض دفعہ ایساہوتاہے کہ کسی انسان پر آفت آتی ہے مگروہ رسوائی کاموجب نہیں ہوتی.اوربعض دفعہ رسوائی توہوتی ہے مگرہلاکت اس کے ساتھ نہیں ہوتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر جب عذاب آئے گاتواس میں دونوں باتیں شامل ہوں گی تباہی بھی اوررسوائی بھی.
Page 70
الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ ظَالِمِيْۤ اَنْفُسِهِمْ١۪ فَاَلْقَوُا (ان پر)جن کی روحوں کو فرشتے (عین )اس وقت کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کررہے ہوتے ہیں نکالتے ہیں.تووہ(یہ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ١ؕ بَلٰۤى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا کہہ کر)صلح کی طرح ڈالتے ہیں(کہ)ہم (تو)کوئی بھی برائی(کاکام ) نہیں کیاکرتے تھے (سوانہیں کہا جائےگا کہ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۰۰۲۹ واقعہ)یوں نہیں بلکہ (اس کے برعکس ہے.یاد رکھو)جوکچھ تم کرتے تھے اُسے اللہ (تعالیٰ)یقیناًخوب جانتاہے حل لغات.السَّلَمُ.اَلْاِسْمُ مِنَ التَّسْلِیْمِ بِمَعْنَی السَّلَام.باب تفعیل سے اسم مصدر ہے اور اس کے معنے وہی ہیں جوسلام کے ہیں یعنی سلامتی.صلح.نیز اس کے معنے ہیں.اَلْاِسْتَسْلَامُ.تابعداری.فرمانبرداری.(اقرب) بَلیٰ:جَوَابٌ لِلتَّحْقِیْقِ تُوْجِبُ مَایُقَالُ لَکَ لِاَنَّھَاتَرْکٌ لِلنَّفْیِ فَاِذَاقُلْتَ لِزَیْدٍ لَیْسَ عِنْدَکَ کِتَابٌ فَقَالَ بَلٰی لَزِمَہُ الْکِتٰبُ واِنْ قَالَ نَعَمْ فَلَایَلْزَمُہُ.یعنی یہ نفی کے بعد آتا ہے.لیکن معنوں کو مثبت کردیتاہے جیسے کوئی کسی کوکہے کہ تیرے پاس کتاب نہیں.توجواب میں وہ بَلٰی کالفظ کہے.تواس کے معنے یہ ہوں گےکہ کیوں نہیں ؟میرے پاس کتاب ہے.لیکن اگرجواب میں نعَمْ کالفظ کہے.تومعنے ہوں گے کہ میرے پاس کتاب نہیں.(اقرب) تفسیر.ظَالِمِيْۤ اَنْفُسِهِمْکہہ کر کفار کو مجرم قرار دیا گیا ہے اس آیت میںبتایاکہ یہ عذاب ان کفار پر آئے گاجو مو ت تک کفرپر قائم رہیں گے.ظَالِمِيْۤ اَنْفُسِهِمْ کہہ کر بتایاکہ ایسے لوگوں کی ساری عمر اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں گذر جاتی ہے اوروہ سمجھتے یہ رہتے ہیں کہ وہ نبیوں پر ظلم توڑ رہے ہیں.گویا ان کی مثال اس درندہ کی سی ہوتی ہے جوپتھر کو چاٹتاہے اوراس کی زبان سے خون بہنے لگتاہے.مگر خون کی لذت کو پتھر کامزاسمجھ کر وہ اس کے چاٹنے میں لگارہتاہے.یہاں تک کہ اس کی ساری زبان ہی گھس جاتی ہے.صلح کو سلم کہے جانے کی وجہ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ.سَلَمَ کے معنے صلح کے ہیں اورصلح کو سلم اس لئے کہتے ہیں کہ
Page 71
اس کے ذریعہ سے ہرایک دوسرے کے شر سے بچ جاتا ہے.فَاَلْقَوُا السَّلَمَ سے یہ مراد ہے کہ وہ یہ دیکھ کر کہ اب تو ہم پکڑے گئے اوربچنے کی کوئی راہ نہیں مصالحانہ باتیں کریں گے.فَاَلْقَوُا السَّلَمَ کے لفظی معنے یہ ہوسکتے ہیں کہ وہ صلح کی طرح ڈالیں گے.مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍمیں بتایاگیا ہے کہ وہ اس وقت یہ توکہہ نہیں سکیں گے کہ ہم نے معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کی.پس وہ اپنے مشرکانہ اعمال کی اس طرح تشریح کریں گے کہ جوکچھ ہم نے کیا بدی کی نیت سے نہیں کیابلکہ نیک نیتی سے کیاتھا.مَا كُنَّا نَعْمَلُکے الفاظ میں کفار کی طرف سے اپنے شرک کرنے میں معذرت میرے نزدیک مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍکے معنے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا.بلکہ یہ کہ ہمار افعل جو بھی تھا وہ بدی کی نیت سے نہ تھا.اس کامحرک سُوْٓءٍ نہیں تھا.بلکہ نیک نیتی سے وہ فعل کیاگیاتھا.اس دنیا میں بھی جب مشرک توحید کے دلائل کے سامنے عاجز آجاتے ہیںتوکہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم توبتوں وغیرہ کو سجدہ خداسمجھ کر نہیں کرتے.بلکہ صرف توجہ کے قیام کے لئے ایسا کرتے ہیںورنہ عبادت توہم اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں.بَلٰۤى اِنَّ اللّٰهَمیں کفار کی معذرت کا جواب بَلٰۤى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ کہہ کر یہ بتلایا ہے کہ یہ تمہار اصر ف ڈھکونسلا ہے.خدا تعالیٰ کوخوب معلوم ہے کہ تم کس نیت اورارادہ سے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے.اللہ تعالیٰ کی تلاش سچے دل سے کرتے توان کی توجہ کے لئے ان جھوٹے سامانوں کی کیاضرورت تھی.نیز یہ بھی بتایا کہ یہ عذر جھو ٹا ہے تم تو فی الواقع مشرک تھے.مَا كُنَّا نَعْمَلُ کے ایک اور معنے مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق کوشش کی اورجو کچھ کیا حق سمجھ کر کیا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے.اگر تم نیک نیتی سے یہ کا م کرتے توہم تم کو ہدایت کیوں نہ دیتے.ہما راتویہ قانون ہے کہ وَالَّذِیْنَ جَاھَدُوْافِیْنَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت :۷۰) جو لوگ صحیح طورپر ہماری تلاش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں.پس اگر تم نیک نیتی سے ہمیں پانے کی کوشش کرتے توغلط راستہ پر کبھی نہ چلتے.ہم خود تم کو ہدایت دیتے.پس اس عذر کی وجہ سے تم سزاسے نہیں بچ سکتے.
Page 72
فَادْخُلُوْۤا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا١ؕ فَلَبِئْسَ مَثْوَى اس لئے (اب )تم جہنم کے دروازو ں میں سے اس میں ہمیشہ کے لئے ٹھکانہ بناتے ہوئے داخل ہو.کیونکہ تکبر الْمُتَكَبِّرِيْنَ۰۰۳۰ کرنےوالوںکا ٹھکانہ یقیناًبہت بُرا(ہوتا)ہے.حل لغات.جَھَنَّمُ.کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر۱۹.جَھَنَّمُ دَارُالْعَقَابِ کا نام ہے.یہ ممنوع من الصرف ہے.بعض کے نزدیک یہ لفظ عجمی ہے.بعض اسے اصل میں فارسی یا عبرانی قرار دیتے ہیں لیکن یہ درست نہیں کہ عربی کے الفاظ کو غیرزبانوں کی طرف منسوب کیا جائے.بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لفظ ایسے قاعدہ سے بنایا گیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی.اس وجہ سے اس کو انہوں نے غیرزبان کا قرار دے دیا.عربی میں جَھَنَ.جُھُوْنًا کے معنے قَرُبَ وَدَنَا کے ہوتے ہیں اور اس سے جَھَنَّمُ بنا ہے یا یہ لفظ جَھَمَ سے بنا ہے.عربی زبان میں زیادۃِ نون فی وسط الکلمہ کی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں.پس جَھَمَ سے جَھَنَّمُ کا بننا خلاف قواعد نہیں اور جَھَمَ کے معنے ہیں اِسْتَقْبَلَہٗ بِوَجْہِ مُکْفَھِرٍّ.کہ اس کو تیوری چڑھا کر ملا اور تَجَھَّمَہُ کے معنے ہیں اِسْتَقْبَلَہٗ بِوَجْہٍ کَرِیْہٍ برے چہرے سے ملا.(اقرب) پس جَھَنَّمُ کے معنے ہوئے ایک ناپسندیدہ جگہ جو ناراضگی سے لینے کو بڑھتی ہے.یہ نام اس کے شعلے مارنے کی وجہ سے رکھا گیا.بِئْسَ.بِئْسَفعل ذم کہلاتاہے.یعنی جب کسی کی مذمت مقصود ہو.اس وقت یہ فعل استعمال کرتے ہیں.جس کی مذمت کی جائے اُسے مخصوص بالذّم کہتے ہیں.اس کے بعد اس کا فاعل آتاہے اورپھر مخصوص بالذّم.فاعل اور مخصوص بالذم دونو ں مرفوع ہوتے ہیں.اس کے فاعل کے لئے ضروری ہے کہ لام جنس کے ساتھ مقرون ہو.یامقرون بلام الجنس کی طر ف مضاف ہو.جیسے بِئْسَ الرَّجُلُ زَیْدٌ اور بِئْس غُلَامُ الرَّجُلِ بِکْرٌ.اور کبھی اس کا فاعل ظاہراً مقرون باللام نہیں ہوتا.بلکہ اس کی جگہ نکرہ منصوب تمییز کے رنگ میںلے آتے ہیں یا مَانکرہ استعمال کرلیتے ہیں.جیسے بِئْسَ رَجُلًا زیْدٌ اور بِئْسَ مَازَیْدٌ میں رَجُلًا اور مَااستعمال ہوئے ہیں (اقرب) مَثْوَی کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۲۲.مَثْوًی ثَوَاءٌ میں سے مصدر میمی یا اسم ظرف ہے جس کے معنے ہیں اَلْاِقَامَۃُ مَعَ الْاِسْتَقْرَارِ کسی جگہ
Page 73
رہائش اختیار کرنا ٹھہرنا.(مفردات) اَلْمَثْوٰی.اَلْمَنْزِلُ.اترنے اور ٹھہرنے کی جگہ (اقرب) تفسیر.اس آیت میں پھر اس امر پر زور دیا ہے کہ جو متکبر ہویعنی حق کو سمجھتا ہو.لیکن شرارت کی وجہ سے اوراس خیال سے کہ میں کیوں نبی کا متبع ہوکر چھوٹابنوںحق کا انکار کرنے والاہووہ بہت سزاپائے گا.بہ نسبت اس کے جو مجر م توہے مگر اس کاجرم شرار ت سے نہیں بلکہ غفلت اورلاپرواہی کی وجہ سے ہے.یہ موجب بھی گومستحق سزابناتا ہے مگر تکبر کے موجب سے کم.بِئْسَ کے معنی زیادہ برے کے ہوتے ہیں.پس اس لفظ سے دونوں قسم کے مجرموں کا فرق بیا ن کیا گیا ہے.وَ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَا ذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ١ؕ اور(جب)ان لوگوں سے جنہوں نے تقویٰ(کاطریق )اختیار کیا ہے کہا گیا (کہ)تمہارے ر ب نے کیا (شاندار قَالُوْا خَيْرًا١ؕلِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ کلام )اتاراہے توانہوں نے کہا (کہ ہاں)بہترین.جنہوں نے نیکو کاری(کی راہ )اختیار کی ان کے لئے اس دنیا الدُّنْيَا حَسَنَةٌ١ؕ وَ لَدَارُالْاٰخِرَةِ خَيْرٌ١ؕ وَ لَنِعْمَ (کی زندگی )میں (بھی) بھلائی (مقدر)ہے.اورآخرت کا گھر (توان کے لئے )اوربھی بہتر ہوگا.اورتقویٰ دَارُ الْمُتَّقِيْنَۙ۰۰۳۱ اختیارکرنے والوں کا گھر یقیناًبہت (ہی )اچھا ہوتا ہے.حلّ لُغَات.خَیْرًا.اَلْـخَیْرُ:وِجْدَانُ الشَّیْءِ عَلٰی کَمَالَاتِہِ اللَّائِقَۃِ.کسی چیز کا اس کے مناسب کمالات سمیت پائے جانے کانام خیر ہے.وَقِیْلَ حُصُوْلُ الشَّیْءِ لِمَا مِنْ شَأْنِہٖ اَنْ یَّکُوْنَ حَاصِلًا لَہٗ اَیْ یُنَاسِبُہٗ ویُلِیْقُ بِہٖ.اوربعض محققین نے کہا ہے کہ کسی چیز کا ایسے طور پر ہونا کہ اس میں اس کے شایا ن شان باتیں پائی جائیں خیر کہلاتا ہے.اَلْمَالُ مُطْلَقًا.مال.اَلْکَثِیْرُ الْخَیْرُ.خیر اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس میں ہرقسم کے کمالات بکثر ت پائے جائیں.(اقرب) نِعْمَ نِعْمَ فعل مدح کہلاتاہے.یعنی جب کسی کی تعریف کرنی مقصود ہو تواس وقت یہ فعل استعمال کیا
Page 74
جاتاہے.جس کی تعریف کی جا ئے اسے مخصوص بالمدح کہتے ہیں ا س کے فاعل اورمخصوص بالمدح کے وہی احکام ہیں جو پہلے بِئْسَ کے متعلق لکھے جاچکے ہیں.(اقرب) تفسیر.قرآن مجید کے متعلق مومنوں کا نقطہ نگاہ اس آیت میں مومنوں کے نقطہ نگاہ کوظاہر کیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے.اگر کوئی کہے کہ وہ تومسلمان تھے انہوں نے تو یہ کہنا ہی تھا ان کی گواہی کوئی وقعت نہیں رکھتی.تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول اس وقت کا ہے جبکہ وہ مکہ میں تھے.چاروں طرف سے ان کو تنگ کیاجاتاتھا اوران کو جان کے لالے پڑ رہے تھے.ایسے وقت میں ان کا اس کتاب کو قبول کرلینا اوراس کے متعلق یہ رائے ظاہر کرنا اس کی سچائی کی نہایت زبردست شہادت ہے.قَالُوْا خَيْرًا.انہوں نے کہا یہ کتاب مناسب کمالات کے ساتھ نازل ہوئی ہے یعنی جو باتیں کسی روحانی کتاب میں چاہئیں وہ سب بتمام و کمال اس میں موجود ہیں.یاجیساخیا ل تھا کہ ایسی کتاب آنی چاہیے اس سے بھی بہتر ا س کو پایا.نقطہ نگاہ بدلنے سے عمل میں فرق اَحْسَنُوْا.اس میں یہ بتایا ہے کہ نقطہ نگاہ کے بدلنے سے عمل میں کتنافرق پڑ جاتاہے.ایک گروہ نے اسے اساطیر الاولین کہا.پس اس کے وعید سے نہ ڈرے اورہلاکت کا شکار ہوگئے.اورمومن جنہوں نے اسے خیر سمجھا وہ اس کی پوری اتباع کرنے میں لگ گئے اورآخر خیر والے مقام یعنی جنت میں پہنچ گئے.وہ مقام کیسا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا گیا ہے.جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا۠ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ (وہ گھر )دائمی رہائش کے باغات( ہیں )جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے اند ر نہریں بہتی ہوں گی.ان لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ١ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَۙ۰۰۳۲ (باغوں)میں جو کچھ و ہ چاہیں گے انہیں ملے گا.تقویٰ اختیار کرنے والوں کواللہ (تعالیٰ)اسی طرح جزاء دیا کرتا ہے.حلّ لُغَات.جَنَّاتُ عَدْن کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر ۲۹.جَنّٰتٌ جَنَّۃٌ کی جمع ہے اور اَلْجَنَّۃُ جَنَّ میں سے ہے.وَاَصْلُ الْجَنِّ سَتْرُ الشَّیْءِ.جَنَّ کے اصل معنے کسی چیز کو ڈھانپنے کے ہیں.یُقَالُ جَنَّہُ اللَّیْلُ چنانچہ جَنَّہُ اللّیْلُ کا محاورہ انہی معنوں میں مستعمل ہے کہ رات نے
Page 75
اس کو ڈھانپ لیا.وَالْجَنَّۃ کُلُّ بُسْتَانٍ ذِیْ شَجَرٍ یَسْتُرُ بِاَشْجَارِہِ الْاَرْضَ.اور جنت ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس میں کثرت سے درخت ہوں اور وہ درختوں کے جھنڈ سے زمین کو ڈھانپ لے.وَقَدْ تُسَمَّی الْاَشْجَارُ السَّاتِرَۃُ جَنَّۃٌ.اور ڈھانپنے اور چھپانے والے یعنی گھنے درختوں کو بھی جَنَّۃٌ کہتے ہیں.وَسُمِّیَتِ الْجَنَّۃُ اِمَّا تَشْبِیْہًا بِالْجَنَّۃِ فِی الْاَرْضِ وَاِنْ کَانَ بَیْنَہُمَا بَوْنٌ.وَاِمَّا لِسَتْرِہِ نِعَمَہَا عَنَّا الْمُشَارَ اِلَیْہَا بِقَوْلِہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّااُخْفِیَ لَہُمْ مِنْ قُرَّۃِ اَعْیُنٍ.اور جنت کو اس لئے جنت کے نام سے پکارا گیا ہے کہ یا تو وہ دنیاوی باغات کے مشابہ ہے اگرچہ ان میں اور اس میں بہت فرق ہے یا اس وجہ سے کہ اس کی نعمتیں ہم سے پوشیدہ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ میں فرمایا ہے کہ جنت کی نعماء کا کسی کو علم نہیں.(مفردات) عَدَنَ بِالْمَکَانِ عَدْنًا: اَقَامَ بِہِ.عَدَنَ کے معنے ہیں کسی جگہ میں ٹھہرا.تَوَطَّنَہٗ.اس کو وطن بنایا.قِیْلَ وَمِنْہُ جَنَّاتُ عَدْنٍ اَیْ جَنَّاتُ اِقَامَۃٍ لِمَکَانِ الْخُلُوْدِ اور بعض محققین لغت نے کہا ہے وَجَنّٰتُ عَدْنٍ میں عدن اقامت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ رہ پڑنے کے باغات.کیونکہ ان میں ہمیشہ رہا جائے گا.(اقرب) تفسیر.یعنی وہ مقام خیر ہمیشہ رہنے والا ہوگا.کیونکہ اچھی چیز کو ہمیشہ رکھاجاتا ہے.تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُکا مطلب تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ.یہ نہیں کہ اس کی تہ میں نہریں بہتی ہوں گی.بلکہ مراد یہ ہے کہ اس میں بہنے والی نہریں اُسی کےنظام کے ماتحت ہوں گی.دنیا میں نہریں اوردریا ضروری نہیں کہ ان لوگوں کے تابع ہوں جن کے ملک یا زمین میں و ہ بہتے ہوں.جب ایسی صورت ہو تو وہ ان سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے.بسا اوقات دریا کئی ملکوں میںسے گذرتے ہیںاو ران سے فائدہ اٹھانے کے لئے ملکوں میں جنگ شروع ہوجاتی ہے.پس ان الفاظ سے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جنت کی نہریں جنت کے نظام کے کلی طورپر ماتحت ہوں گی اورکوئی دوسرا ان میں شریک نہ ہوگا.جَنّٰتُ عَدْنٍ سے اس مقام کے بے نقص ہونے کی طرف اشارہ ہے جَنّٰتُ عَدْنٍسے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ ایسا مقام ہے جس میں کوئی نقص نہیں.کیونکہ فنا کاموجب نقص ہی ہوتا ہے.لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ کے دو معنی لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ.اس کے دومعنے ہوسکتے ہیں (۱)ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی کیونکہ ان کی مشیّت مشیّتِ ایزدی ہوگی.گویا مَاتَشَآءُ وْنَ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللہُ (الدھر:۳۱) کی حالت ہو گی.اوران کے دل میں انہی اشیاء کی خواہش پیداہوگی جو ان کو مل سکتی ہوں گی اورمل جائیںگی.حرص و آز سے ان کے دل خالی ہوں گے اورحسد کی آگ سے وہ محفوظ ہوں گےاورہرگندگی سے دل پاک
Page 76
ہوجائیں گے.(۲)ان کو ان جنتوں کے متعلق جن میں و ہ رکھے جائیں گے پورااختیار حاصل ہوگا.اوران کے متعلق ان کے دل میں جو خواہش پیداہوگی وہ ضرورپوری ہو گی کیونکہ انہیں وہاں پورااختیار دیاجائے گا.الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ طَيِّبِيْنَ١ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ (وہ متقی )جن کی روحوں کو فرشتے اس حالت میں کہ وہ پاک نفس ہوں (یہ )کہتے ہوئے قبض کرتے ہیں کہ عَلَيْكُمُ١ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۰۰۳۳ (اب)تمہارے لئے سلامتی (ہی سلامتی)ہے.جوکچھ (تم )کرتے تھے اس کے مطابق تم جنت میں داخل ہوجائو.حل لغات.سَلَامٌ:سَلَامُ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۱۱.سَلَامٌ کے کئی معنی ہیں.اِسْمٌ مِنَ التَّسْلِیْمِ.باب تفعیل سے اسم مصدر ہے اور اس کے معنی سلامتی دینے کے ہیں.اِنْقِیَادٌ یعنی فرمانبرداری.سلام خدا کا نام بھی ہے.کیونکہ وہ تمام عیبوں اور نقصوں سے پاک ہے.(الحشر ع۴) تفسیر.یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جن کوموت اس وقت کہ وہ طیب النفس ہوتے ہیں آتی ہے.وہ ہرقسم کے نقصوں سے پاک ہوتے ہیں.ہرقسم کی خوبیاں.صفائی.ترقی اورعلوّہمت کے جذبات ان میں پائے جاتے ہیں (طیبین کے معنوں کے لئے کلمہ طیبہ کی تفسیر سورئہ ابراہیم رکوع۴ میں دیکھو) یَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌعَلَیْکُمْ.یعنی کفار توخود ڈر کر صلح کی طرح ڈالیں گے اورمومنوں کو فرشتے خود بڑھ کر سلام کہیں گے.
Page 77
هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ (اب)یہ (لوگ )اس بات کے سوا کس کاانتظارکررہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس( آسمانی عذاب لےکر)آئیں یا رَبِّكَ١ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ١ؕ وَ مَا ظَلَمَهُمُ تیرے رب کا (فیصلہ کن) حکم آجائے.اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے (زمانوں کے)تھے اور اللّٰهُ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤااَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ۰۰۳۴ اللہ( تعالیٰ)نے ان پر (کوئی )ظلم نہیں کیاتھا بلکہ وہ (خود ہی )اپنی جانوںپر ظلم کرتے تھے.تفسیر.کفار پر فردی اور قومی عذاب کے آنے کی طرف اشارہ یعنی یہ کفار اب اپنی مدت گزارچکے ہیں.اب تو یہ صرف ان عذابوں کاانتظار کررہے ہیں جو (۱)فردی طور پر ان پر آنے والے ہیں جیسا کہ اوپر کی آیا ت سے ظاہر ہے ملائکہ کا آنا فردی عذاب پر دلالت کرتا ہے.(۲)اس عذا ب کاانتظارکررہے ہیں جوقومی طورپر ان پر نازل ہوگا.اَمْرُ رَبِّکَ سے اسی طرف اشار ہ ہے.وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ.یعنی اپنے اعمال سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنانے کافعل پہلے کفار بھی کرتے رہے ہیں.یہ بھی ویسا ہی کررہے ہیں.مگراس کانقصان انہی کی جانو ںکو پہنچے گا.نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے.فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ پس ان کے عملوں کی سزانے انہیں آپکڑ ا.اورجس (عذاب کی خبر)پر وہ ہنسی کیاکرتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا يَسْتَهْزِءُوْنَ۠ؒ۰۰۳۵ (اورتباہ کردیا ).حل لغات.حَاقَ بِھمْ.حَاقَ بِہٖ کے معنے ہیں اَحَاطَ بِہِ کسی چیز کااحاطہ کرلیا.(اقرب) یَسْتَھْزءُ وْنَ.یَسْتَھْزِءُ وْنَ اِسْتَھْزَأ سے جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے مزید تشریح کے لئے دیکھیں رعد آیت نمبر۳۳.
Page 78
اُسْتُھْزِیءَ اِسْتَھْزَأَ سے مجہول کا صیغہ ہے اور اِسْتَھْزَأَ ھَزَأَ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.جس کے معنے ہیں سَخِرَمِنْہُ اس سے ٹھٹھا کیا.(اقرب) تفسیر.سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا میں عذاب الٰہی کی فلاسفی بیان کی گئی ہے سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا سے مراد عمل کے بدنتائج ہیں اوربتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالمانہ عذاب نہیں دیتا.بلکہ کافر خود اپنی سزاپنے عمل سے پیداکرتا ہے.عذاب الٰہی کوئی بیرونی چیز نہیں بلکہ بدعمل انسان کے عمل کاطبعی نتیجہ ہے.ا س میں عذاب الٰہی کی فلاسفی بیان کی گئی ہے.یہی عذاب ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا.ورنہ وہ عذاب جوطبعی نتائج کی قسم سے نہیں ہوتا بسا اوقات قابل اعتراض ہو جاتا ہے جیسے بعض دفعہ دنیاوی مجسٹریٹ مجرم کو سزادیتاہے تولوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے جرم سے زیادہ سزادے دی ہے.مگر بدپرہیزی سے جو بیماری پیداہوتی ہے اس کی نسبت کوئی نہیں کہتاکہ وہ بدپرہیزی کی مناسب سزانہیں.کیونکہ ہر اک جانتا ہے کہ وہ طبعی نتیجہ ہے اوراپنی حد سے بڑھ سکتا ہی نہیں.حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۠ سے بتایا ہے کہ کفار جس قسم کے اعتراض نبیوں پر کرتے ہیں ویسے ہی حالات میں سے انہیں گذرناپڑتا ہے.اگروہ انہیں جھوٹاکہتے ہیں توخود جھوٹ کے الزام کے نیچے آتے ہیں اگربدکار کہتے ہیں توخود ان کی بدکاریاں کھولی جاتی ہیں.وَ قَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ اورجن لوگوں نے شرک(کاطریق اختیار)کیا انہوں نے (یہ بھی )کہا ہے کہ اگر اللہ (تعالیٰ یہی )چاہتا (کہ اس مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَ لَاۤ اٰبَآؤُنَا وَ لَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ کے سواکسی کی عبادت نہ کی جائے)تونہ ہم(ہی)اس کے سواکسی چیز کی عبادت کرتے اورنہ ہمارے باپ داداایسا شَيْءٍ١ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ١ۚ فَهَلْ عَلَى کر تے اورنہ (ہی )ہم اس کے (فرمانے کے )بغیر کسی چیز کو (خودبخود)حرام ٹھہراتے جو(لوگ)ان سے پہلے
Page 79
الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۰۰۳۶ (سچائی کے دشمن )تھے انہوں نے (بھی )ایسا ہی کیاتھا.بھلا(کیا یہ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ)رسولوں پر(خدا کاپیغام) پہنچادینے کے سوا(اور)کیاذمہ واری ہے.تفسیر.اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سےوَ لَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ بیان ہوچکا ہے.یعنی کفار یہ نہ خیال کریں کہ کج راستے کیوں بنے ہیں.یہ راستے انہوں نے خود بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے.اللہ تعالیٰ توجبر سے کام نہیں لیتااگر لیتاتوہدایت دیتا.اب خودکفار کے منہ سے وہی اعتراض نقل کیا گیا ہے.فرماتا ہے کافر کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم یا ہمارے باپ دادے شرک نہ کرتے.پس جب اس نے روکا نہیں تومعلوم ہواکہ وہ ہمارے شرک کو ناپسند نہیں کرتا.قرآنی دلائل سے عاجز آکر کفار کے غیر معقول اعتراضات جوشخص یاجماعت بھی غلط عقائد اختیار کرے اسے دلائل کے سامنے دب کر غیر معقول رویہ ہی اختیار کرناپڑتا ہے.اوراس کے مقا بلہ کی بنیاد کسی مقر رہ اصل پر نہیں ہوتی بلکہ اسے حملہ کے مطابق جگہ بدلنی پڑتی ہے.رکوع تین کے آخر میں بتایاگیاتھا کہ کفارتنگ آکر کہتے ہیں کہ بڑی اعلیٰ تعلیم لئے پھرتے ہو آخر یہ تعلیم پہلوں کی کتب سے نقل کی ہوئی ہے اورہے کیا ؟ اس کے دوجواب دیئے گئے تھے اول تویہ کہ یہ اعتراض محض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ہے ورنہ اس میں کوئی حقیقت نہیں.یعنی اگر نقل بھی ہو تو بھی اگر سچی بات ہے تومانتے کیوں نہیں.دوسراجواب یہ دیاتھا کہ اگریہ نقل ہے توتم بھی توپہلے انبیاء کے مخالفین کی نقل کررہے ہو.وہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھےمگر نہ وہ کامیاب ہوسکے نہ تم کامیاب ہوسکتے ہو.یہ عملی ثبوت ان کے اعترا ضات کے بوداہونے کادیا کیونکہ اگرمعقول اعتراض ہوتااورانبیاء کی تعلیم واقع میں محض نقل ہوتی تودنیا اپنے پہلے مذاہب کو چھو ڑکر انہیں اختیارکیوں کرتی.اس کے بعد کفار اورمسلمانوں سے جو الگ الگ قسم کے سلوک ہونے والے تھے ان کا ذکر کیا ہے.کفار کا اپنے اعتراضوں کو غیر مؤثر پا کر پہلو بدلنا اس کے بعد پھر کفار کے اعتراضوں کی طرف رجوع کیا گیا ہے اوربتایا ہے کہ جب کفار اپنے پہلے اعتراض کا جواب سنتے ہیں اورسمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض مؤثر نہیں ہوسکتا تووہ پھر پہلو بدلتے ہیں اورکہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سزاکیوں دینے لگا.کیاخدا تعالیٰ قادر نہیں.پھر اگروہ ہمارے
Page 80
طریق کو غلط سمجھتا ہے توہمیں اورہمارے باپ دادوں کو اس سے ہٹاکیوں نہیں دیتااورشرک کی توفیق ہم سے کیوں نہیں چھین لیتا.اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتاہے کہ اس کا ذریعہ ایک ہی ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جن انبیاء کو بھیجتا انہیں جبر کرنے کی تلقین کرتا.لیکن کافر بھی توبعض نبیوں کومانتے ہیں کیا وہ کو ئی نبی پیش کرسکتے ہیں جس نے جبر سے کام لیا ہو.حالانکہ ان کے مخالفوںکو یہ بھی غلطی پر سمجھتے ہیں.پس اگران کے مسلّمہ نبیوں (مثلاً حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہما السلام)نے جبر سے کام نہیں لیااورخدا تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق نہ دی کہ وہ اپنے مخالفوںکو زبردستی منوالیتے.تو اب اس امر کی کیوں توقع رکھتے ہیں جس طرح ہمیشہ سے انبیاء محض تبلیغ سے کام لیتے آئے ہیں.اب بھی اسی طرح ہوگا.تعجب ہے اس آیت کی موجودگی میں بعض مسلمان دین میں جبر کوجائز سمجھتے ہیں (مرتد کی سزا اسلامی قانون میں مصنف ابوالاعلیٰ مودودی ص ۵۰)حالانکہ یہ امر قرآن کریم کی متعددآیات کے خلاف ہے.وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اورہم نے یقیناً ہر قوم میں (کوئی نہ کوئی)رسول (یہ حکم دےکر )بھیجا ہے کہ تم اللہ (تعالیٰ) کی عبادت کرو.اورحد اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ١ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَ مِنْهُمْ سے بڑھنے والے سرکش سے کنار ہ کش رہو.اس پر ان میں سے بعض (تو)ایسے (اچھے ثابت)ہوئے کہ انہیں مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ١ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا اللہ (تعالیٰ)نے ہدایت دی اوربعض ایسے کہ ان پر ہلاکت واجب ہوگئی.پس تم (تمام)ملک میں پھر و اور دیکھو کہ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ۠۰۰۳۷ (انبیاء کو )جھٹلانے والوں کاانجام کیساہواتھا.حَلّ لُغَات.اِجْتَنِبُوا اِجْتَنِبُوااِجْتَنَبَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِجْتَنَبَہٗ کے معنے ہیں بَعُدَ عَنہٗ.اس سے دور ہوگیا.(اقرب) الطَّاغُوْت:الطّاغُوتُ کلُّ مُتَعَدٍّ.حد سے بڑھنے والا.کُلُّ رأسٍ ضَلَالٍ.ہرشخص جو گمراہی کا سردار
Page 81
ہو.اَلْکَاھِنُ.کاہن.اَلشَّیْطَانُ.شیطان.اَلْاَصْنَامُ.بت.کُلُّ مَعْبُوْدٍ مِنْ دُوْنِ اللہِ.معبود باطل.مَرَدَۃُ اَھْلِ الْکِتٰبِ.اہل کتاب میں سے سرکش لوگ.اس کی جمع طَوَاغِیتُاورطَوَاغٍ آتی ہے (اقرب) الطَّاغُوتُ : السَّاحرُ.ساحر.اَلْمَارِدُ مِنَ الْجِنِّ.جنّات میں سے سرکش.اَلصَّارِفُ عَنِ طَرِیْقِ الْخَیْرِ.نیکی سے روکنے والا (مفردات) ھَدٰی کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر ۲۸.یَھْدِی ھَدٰی سے ہے اور ھَدَاہٗ الطَّرِیْقَ وَاِلَیْہِ وَلَہٗ کے معنے ہیں بَیَّنَہٗ لَہٗ وَعَرَّفَہٗ بِہٖ.راستہ دکھایا ، بتایا اور واضح کیا.ھَدٰی فُلَانًا: تَقَدَّمَہٗ اس کے آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لے گیا.ھَدَاہٗ اللہُ اِلَی الْاِیْمَانِ اَرْشَدَہٗ.ایمان کی طرف رہنمائی کی.(اقرب) العاقِبۃُ.اٰخِرُ کُلِّ شَیْءٍ.ہرچیز کاآخر.انجا م.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں کفار کے اعتراضات کے پانچ جوابات اس آیت میں کفارکے مذکورہ بالااعتراض کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں.پہلاجواب یہ دیا گیا ہےکہ ہم ہر قوم میں رسول مبعوث فرماچکے ہیں.اوران میں سے ہر اک نے توحید کی ہی تعلیم دی ہے.پس اگر تمہارایہ دعویٰ درست ہے کہ خدا تعالیٰ شرک کو بھی کسی حالت میں پسند کرسکتا ہے توبتائو کہ سب کے سب نبی شرک کے خلاف کیوں رہے اورکیوںتوحید کی تعلیم دیتے رہے.اگر شرک بھی خدا تعالیٰ کی تصدیق کی مہر رکھتاہے توکوئی نبی توشرک کی تعلیم دینے والابھی آتا.دوسراجواب بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ کے الفاظ میں دیا یعنی اگر جبر ہوتا تو پھر ایک ہی رسول کافی تھا جو ان لوگوںکو جنہیں ہدایت پر چلانامقصود تھا ہدایت دے دیتا.بار بار اورہرقوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت توتبھی ہوئی جبکہ لوگ بار بار نبیوں کے راستے کو چھو ڑگئے.جبر کی صورت میں یہ امر ممکن نہ تھا.تیسراجواب یہ دیاکہ ہرنبی کی تعلیم میں بد صحبت سے بچنے کا حکم موجود ہے اوربرے آدمیوں کو نہ ماننے کی تعلیم ہے.یادوسرے لفظوںمیں شیطان کے حملہ سے محفوظ رہنے کا ارشاد ہے اگر یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو موحد بنادیا اوربعض کو مشرک.اوراس دنیا میں جبر سے ہی کام لیاگیا ہے تواس تعلیم کے کیا معنے ہوئے.اگر ہر اک شخص جس مذہب اوراصل پر ہے خدا تعالیٰ نے ہی اُسے اس مقام پر کھڑا کیا ہے اوراس کا اس میں اختیار نہیں تونبی بھیج کر ہوشیارکرنے کافائدہ کیا.جو موحد ہے موحد رہے گااورجو مشرک ہے مشرک ہی رہے گا.چوتھاجواب یہ دیاہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے ان کے پیغام کو مان لیا حالانکہ پہلے وہ کافر تھے
Page 82
اور کچھ نے نہ مانا.اب اگر یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ نے جوکچھ کسی کو بنادیا بنادیا.توہرنبی کے زمانہ میں ایک جماعت ایمان کیوں لاتی رہی.اگر خدا تعالیٰ نے انہیں کافر بنادیاتھا توانہیں ایمان کس طرح نصیب ہوا.پس ہرنبی کے زمانہ میں کافروں کی ایک جماعت کا مومن بن جانا ایک عملی ثبوت ہے اس امر کاکہ خدا تعالیٰ نے جبراً کسی کو کافر نہیں بنایا.پانچواں جواب یہ دیا کہ ہرنبی کے دشمن ہلاک ہوتے چلے آئے ہیں دنیا ان کے نشانوں سے معمور ہے.علم نہ ہوتو دنیا میں پھر کردیکھ لو اب اگر تمہارایہ دعویٰ صحیح ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی بعض لوگوں کو کافر یا مشرک بنایا ہے تووہ لوگ تو مجبورمحض تھے انہیں سزادینا کس طرح جائز ہوسکتاتھا پس ان الٰہی عذابوں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو مشرک یا کافر نہ بنایا تھا.بلکہ وہ اپنی مر ضی سے مشرک یاکافر بنے تھے.اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ (اے رسول)اگر تو ان (لوگوں )کی ہدایت یابی کی بہت خواہش رکھتاہے تو(سمجھ لے کہ )جولوگ (دوسروں کو يُّضِلُّ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ۰۰۳۸ دانستہ) گمراہ کررہے ہوں انہیں اللہ (تعالیٰ)ہرگزہدایت نہیں دیتا.اورنہ ان کاکوئی مددگار ہوتاہے.تفسیر.اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع سے خطاب اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے اتباع سے خطاب ہے کہ تم میں سے ہر اک ان کفار کی ہدایت چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر اک کو ہدایت نہیں دے سکتا.کیونکہ جس طرح و ہ جبر سے کافر مشرک نہیں بناتاجبر سے مومن موحد بھی نہیں بناتا.کیونکہ اس طرح ایمان کی غرض باطل ہوجاتی ہے یعنی قلبی صفائی پیدا نہیں ہوتی.پس وہ تم کو بتادیناچاہتاہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں وہ جبر سے ہدایت نہ دے گا.بلکہ ان کے مددگاروں کے سلسلہ کو بھی کاٹ دے گا.لفظ حرص کا استعمال اور اس کے معنے اس آیت میں حرص کالفظ استعمال ہواہے.اس سے دھوکانہیں کھاناچاہیے.حرص کے معنے اردو میں برے ہوتے ہیں لیکن عربی میں صرف شدید خواہش کے ہوتے ہیںاوریہ اپنے استعمال کے موقعہ کے لحاظ سے اچھے اوربرے دونوں معنے دیتاہے.اگربرے کام کے لئے اس لفظ کواستعمال
Page 83
کیا جائے تو اس کے معنے برے ہوتے ہیں.اوراگراچھے کام کے لئے اس لفظ کااستعمال ہوتوا س کے معنی اچھے ہوتے ہیں گویا یہ لفظ ذاتی معنے کوئی نہیں رکھتا.ا س نسبت کے مطابق اس کے معنے ہوتے ہیں جو جملہ میں اسے حاصل ہوتی ہے.یہاں چونکہ خیر خواہی کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہواہے.اس لئے اس کے معنے اس جگہ اچھے ہیں.یُضِلُّ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ مَنْ کی طرف ہے فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ.اس میں یُضِلُّ کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف نہیں پھر تی اوریہ معنے نہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا کیونکہ اسی مضمون کو توپہلی آیت میں رد کیا گیا ہے.پس ضمیر مَنْ کی طرف پھرتی ہے.اورمراد یہ ہے کہ جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا.اس جملہ میں اس طرف بھی اشار ہ ہے کہ ہدایت توتوجہ سے ملتی ہے جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے لئے ہدایت کے کب طلب گا ر ہوسکتے ہیں اورجب دل میں تبدیلی نہ ہو توہدایت کس طرح ملے.مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.اس سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نصرت تو انسان کوہدایت کے معاملہ میں سوائے خداکے کوئی دیتاہی نہیں.مگریہ لوگ ہدایت کے ذریعہ کو بند کرچکے ہیں.اگریہ سمجھیں کہ ان کو خود بخود ہدایت ہوجائے گی تویہ غلط بات ہے.ان کی اصلاح محض اس طرح ہوسکتی تھی کہ یہ اسلام کوقبول کرتے.مگر یہ لوگ توبتوں کو ہدایت کاذریعہ قرار دیتے ہیں اس لئے ان کی ہدایت مشکل ہے.اورجب یہ خدا تعالیٰ سے منہ موڑکر جھوٹے معبودوں کی طرف متوجہ ہیں.تو خدا تعالیٰ توان کی مدد کرے گانہیں.باقی رہے ان کے معبود وہ ان کی مدد کرہی نہیں سکتے.پس ان کاکوئی بھی مدد گار نہ ہوگا.وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ١ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ١ؕ اورانہوں نے اللہ (تعالیٰ)کی بڑی زوردارقسمیں کھائی ہیں (کہ )جو مرجائے اللہ (تعالیٰ)اُسے (پھر )زندہ نہیں بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَۙ۰۰۳۹ کرے گا(مگرحقیقت)یوں نہیں یہ (تو ایک ایسا)وعدہ ہے جس (کے پوراکرنے )کاوہ ذمہ وار ہے.لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو )نہیں جانتے.حل لغات.جَھْدَ اَیْمَانِھِمْ جَھَدَ فِی الْاَمْرِ (یَجْھَدُ جَھْدًا) کے معنے ہیں جَدَّ وَتَعِبَ فِیہِ.کسی
Page 84
معاملہ میں خوب محنت اورکوشش سے کام لیا.جَھَدَ دابَّتَہٗ:بلغَ جَھْدَھَا وحَـمَّلَھَا فَوْقَ طَاقَتِھا.جانورپر بہت بھاری بوجھ لادا.اَلْجَھْدُ مصدرہے نیز اس کے معنے ہیں اَلطَّاقَۃُ.طاقت.یُقَالُ ’’اَفْرَغَ جَھْدَہٗ‘‘اَیْ طَاقَتَہٗ چنانچہ اَفْرَغَ جَھْدَہُ کافقرہ بول کر جھد سے مراد طاقت لیتے ہیں.اَلْمَشَقَّۃُ.مشقت (اقرب) اَقْسَمُوْابِاللہِ جَھْدَ اَیْمَانِھِمْ.اَیْ بَالَغُوْافی الْیَمِیْنِ وَاجْتَھَدُوْا یعنی انہوںنے بڑی زوردار قسمیں کھائیں (اقرب) لَایَبْعَثُ: بَعَثَ سے مضارع یَبْعَثُ آتاہے اورلَایَبْعَثُ مضارع منفی ہے.بعث کی تشریح کے لئے دیکھو حجر آیت نمبر ۳۷.یُبْعَثُوْنَ بَعَثَ سے جمع مذکر غائب مجہول کاصیغہ ہے.اوربَعَثَہٗ(یَبْعَثُ بَعْثًا)کے معنے ہیں اَرْسَلَہٗ اس کو بھیجا.بَعَثَہُ بَعْثًا: اَثَارَہٗ وَھَیَّجَہٗ.اس کو اُٹھایااورجوش دلایا.بَعَثَ اللہُ الْمَوْتٰی:اَحْیَاھُمْ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا.بَعَثَہٗ عَلَی الشَّیْءِ : حَمَلَہٗ عَلٰی فِعْلِہِ.اس کو کسی کام کے کرنے پر اُکسایا.اَلْبَعْثُ:النَّشْرُ اُٹھانا.(اقرب) تفسیر.کفار کا دلائل سے عاجز آکر قسمیں کھانا فرمایایہ لوگ جب دلائل سے عاجز آجاتے ہیں توقسمیں کھانے لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں تاکہ اپنے اتباع کو عذاب سے محفوظ رہنے کایقین دلائیں.اورسچ کی جستجو سے غافل کردیں.کفار کی قسمیں کھانے کی وجہ اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار قسمیں کیوں کھاتے ہیں ایسی قسموں کاکیا فائدہ تھا.ا س کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ کمزورطبیعت کے ہوتے ہیں وہ خودفیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے.آئمۃ الکفر کا قسمیں کھا کر عوام کو ان کے سابق عقیدہ پر قائم رکھنا جب سچے مذہب کے دلائل سن کر ان کے دل متذبذب ہوجاتے ہیںتوان کے سردار اورلیڈر قسمیں کھا کھا کر انہیں اپنے سابق عقیدہ پر پکا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چونکہ ان لوگوں میں عزم نہیں ہوتا.کچھ ان میں سے ان قسموں سے مرعوب ہوکر پھر اپنے پرانے خیالات کی طرف عود کرجاتے ہیں.پس یہ بھی لوگوں کو ہدایت سے محروم کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو کفار کے سردار ہمیشہ سے استعمال کرتے چلے آئے ہیں.عوام الناس اس امر کو نہیں سمجھتے کہ قسم تواس شخص کی قابل اعتبار ہوتی ہے جو نیک ہو اورصرف مزید زوردینے کے لئے ہوتی ہے.ورنہ جھوٹے لوگ جس طرح بغیر قسم کے جھوٹ بولتے ہیں قسم کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں.یاپھرقسم شہادت کافائد ہ دیتی ہے یعنی جن امور میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسم پر اس دنیا میں گرفت کرنے کافیصلہ کیا ہو.ان کے متعلق جھوٹی قسم کھانے والا اگر عذاب سے محفوظ رہے تویہ اس کے
Page 85
سچےہونے کاثبوت ہوتا ہے.ورنہ ہرقسم کی نہ اس دنیا میں سزاملتی ہے نہ وہ کوئی دلیل ہوتی ہے.اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدالت دینی میں جھوٹی قسم کھانے والے سزاپاتے ہیں.یعنی ہر اک کو اس دنیا میں سزانہیں ملتی.لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ (یہ دوبارہ زندگی اس لئے ہوگی کہ )تاوہ ان پر اس (حقیقت) کو ظاہرکرے جس میں وہ (آج) اختلاف کررہے كَفَرُوْۤا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ۰۰۴۰ ہیں اورتاجن لوگوں نے کفر (کاطریق )اختیار کیا ہے انہیں معلوم ہوجائے کہ وہ جھوٹے تھے.تفسیر.بعث بعد الموت کی ضرورت اس میں اوپر کے مضمون کی دلیل بیان فرمائی گئی ہے اوروہ یہ کہ حشر بعد الموت مذہبی امورمیں یقین پیداکرنے کے لئے ضروری ہے.اس دنیا میں تواختلاف کبھی مٹتا نہیں.ہمیشہ ہی بعض لوگ مدعیان نبوت کے منکر ہوتے ہیں اوربعض مومن.اگر اسی دنیا تک انسانی زندگی ختم ہوجائے تواول تونبی کے دعویٰ کے متعلق کامل انکشاف نہ ہو اوراس کاامر مشتبہ رہے دوسرے وہ طبقہ جو منکر ہے وہ ہمیشہ کے لئے ہدایت سے محروم رہ جائے اوریہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے.اختلاف کو دور کرنے اور منکرین کے عبد بنائے جانے کے لئے بعث بعد الموت ضروری ہے اس نے تو سب انسانوں کو عبد بننے کے لئے پیدا کیا ہے.اگراسی دنیا میں انسانی زندگی ختم ہوجائے توپھر منکر کبھی عبد نہیں بن سکتے.اس لئے ضرور ہے کہ ایک اورزندگی انسان کو ملے.جس میں حقیقت واضح کردی جائے تاسب لوگوں پر حقیقت کھل جائے اورجو اس دنیا میں حق کے سمجھنے سے محروم رہے ہیں اس دنیا میں حق کو سمجھنے کے قابل ہوجائیں.تبیین کے لئے بعث بعد الموت کی ضرورت پر اعتراض اور اس کا جواب اس آیت پر یہ اعتراض کیاجاسکتاہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں اورآسمانی کتب کی نسبت بھی فرماتا ہے کہ وہ تبیین کرتی ہیں پس جب تبیین یہاں ہوجاتی ہے تواس کے کیا معنے ہوئے کہ بعث بعد الموت کی اس لئے ضرورت ہے کہ جن امور میں اختلاف ہے.اس کے متعلق اللہ تعالیٰ تبیین کردے.اس دنیا میں تبیین کادعویٰ خود اسی سورۃ میں کیا گیا ہے فرماتا ہے وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ(النحل :۶۵) یعنی ہم نے تجھ پر یہ کامل کتاب صر ف اس لئے اتاری ہے
Page 86
کہ جس بارہ میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کے متعلق توانہیں حقیقت کھول کرسنادے.پس سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں حقیقت کھول دی گئی تواگلے جہان کی ضرورت نہ رہی.اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا کے متعلق جب تبیین کالفظ استعمال ہوتاہے تواس کے معنے عقلی طورپر اوردلائل سے حقیقت کے کھول دینے کے ہوتے ہیں اورایسی تبیین صرف ان لوگوں کے لئے کافی ہوتی ہے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں.مگرجولوگ حق کے متلاشی نہ ہوں ان کے لئے یہ تبیین مفید نہیں ہوتی.پس ان کے لئے ایسی تبیین کی ضرورت ہے جو ا س قدر واضح ہو کہ اس کے بعد انکار کی گنجائش نہ رہے.اوربہانہ سازی کاموقعہ ہی باقی نہ رہے.یہ تبیین اس دنیا میں نہیں ہوسکتی.کیونکہ ایسی تبیین کے بعد اعلیٰ ایما ن نصیب نہیں ہوسکتا.جس طرح سورج کو سورج ماننا کوئی اعلیٰ خوبی نہیں.اسی طرح ایسے اظہارحق کے بعد ایمان کے اعلیٰ مقامات حاصل نہیں ہوسکتے.پس انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کو حاصل کرناچاہتے ہیں.ان کو موقعہ دینے کے لئے نبیوں والی تبیین تو اس دنیا میں ہوجاتی ہے اورسب بنی نوع انسان پر صداقت ظاہرکرنے کے لئے وہ تبیین جس کا ذکر اس آیت میں ہےاگلے جہان میں ہوتی ہے.ایسی تبیین کے بعد ایمان خاص نفع نہیں دیتا.ہاں کفا ر کو اس قابل بنادیتاہے کہ سزابھگتنے کے بعد خدا تعالیٰ کی بخشش کوحاصل کرلیں.غرض اس آیت میں یہ بتایاہے کہ وہ تبیین جو سب کو ایما ن دےدے اس دنیا میں ہونہیں سکتی.پس ایک اورجہان کی ضرورت ہے جہاں اس تبیین کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے.ایسی تبیین جس کا کوئی انکار نہ کر سکے بعث بعد الموت کے وقت ہوگی وَلِیَعْلَمَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اس جملہ سے پہلی دلیل کوواضح کیا ہے اوربتایا ہے کہ اس جگہ جس تبیین کاہم نے ذکر کیا ہے.وہ ایسی تبیین ہے جس کے بعد کافر انکار کرہی نہیں سکتا.اوراپنے جھوٹے ہونے کااسے یقین ہو جاتا ہے نہ کہ عام تبیین جس کا ذکر دوسری آیات میں کیاگیاہے.اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَاۤ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ ہماراقول کسی (ایسی )چیز کے متعلق جس(کے پوراکرنے)کاہم ارادہ کریں صرف یہ ہوتاہے کہ ہم اس کے متعلق کہہ فَيَكُوْنُؒ۰۰۴۱ دیتے ہیں کہ ہوجا تووہ ہوجاتی ہے.تفسیر.قیامت کے انکار کی وجہ فرمایا ایک وجہ قیامت کے انکار کی یہ ہے کہ لوگ اسے ناممکن
Page 87
سمجھتے ہیں.حالانکہ اس دنیا میں جو ہماری طاقت کااظہار ہورہا ہے.اس سے وہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی بات انہونی نہیں.ہم توجب کسی امر کے متعلق کہتے ہیںکہ ایساہوجائے ویساہی ہو جایاکرتاہے.پھر قیامت پر کیوں شک ہے.پیشگوئیوں کو قیامت کے لئے بطور دلیل بیان کیا گیا ہے اس جگہ ان پیشگوئیوںکو قیامت کی دلیل کے طورپرپیش کیا ہے جو اس دنیا میں نبی کرتے ہیں اورباوجودحالات کے خلاف ہونے کے وہ پوری ہوتی ہیں.اوراللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کو ثابت کردیتی ہیں.فرماتا ہے ان پیشگوئیوں پر قیاس کرکے تم قیامت کے امکان کو بھی سمجھ سکتے ہو.لفظ كُنْ سے مراد كُنْ.بعض لوگوںکو ا س آیت کے بارہ میں یہ شبہ پیداہواکرتا ہے کہ کُنْ کہنے سے کیامراد ہے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز موجود ہی نہ تھی توپھر حکم کس کو دےدیا.لفظ كُنْ سے آریہ اصحاب کا غلط استدلال آریہ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتاہے کہ پہلے کوئی ماد ہ موجود تھاتبھی تواللہ تعالیٰ نے اس پرحکومت کی.جوچیز ہے ہی نہیں وہ اسے حکم کس طرح دے سکتا ہے (ستیارتھ پرکاش اردو ترجمہ باب ۱۴ ص ۶۹۰).مگر یہ استدلال ان کا غلط ہے کیونکہ اس آیت کاو ہ ترجمہ جس پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ ہے ’’جب ہم اراد ہ کرتے ہیں اس چیز کا جس کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ و ہ ہوجائے.اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ہوجا.پس وہ ہوجاتی ہے‘‘.ظاہر ہے کہ ان الفا ظ پر اوپر کااعتراض اس صورت میں بھی کہ مادہ کو پہلے سے موجود مانا جائے وارد ہوتاہے.کیونکہ خواہ پہلے سے موجود مادہ سے ہی کسی چیز کو بنایاجائے جب تک اس کی وہ نئی صورت نہ بنے جسے بنانے کااراد ہ کیا گیاہو اسے کو ئی حکم نہیں دیاجاسکتا.غرض آریوں کا اس آیت سے اپنے حق میں استدلال بالکل باطل ہے کیونکہ مادہ کوموجودماننے کی صورت میں بھی وہی اعتراض باقی رہتاہے جسے وہ دور کرناچاہتے ہیں جس سے ثابت ہوجاتا ہے کہ آیت کے و ہ معنے ہی نہیں جو اوپر کئے گئے ہیں.بلکہ آیت کے معنے ہی کچھ اورہیں.آنحضرت ؐ کا ایک واقعہ میں لفظ كُنْ کا استعمال وہ صحیح معنے کیا ہیں؟ اسے سمجھنے کے لئے کُنْ کے معنوں کو پہلے صاف کرلینا ضروری ہے کُنْ کے عربی زبان میں کئی معنے ہوتے ہیں جن میں سے ایک معنے ’’ ایسا ہو جائے‘‘کے ہیں.اس کاثبوت مندرجہ ذیل واقعہ سے ملتا ہے.تاریخ میں آتاہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو روانہ ہوگئے.توبعض صحابہؓ پیچھے رہ گئے.ان میں سے ایک ابو خیثمہ بھی تھے.یہ بہت نیک تھے.ان کا
Page 88
خیال بھی نہ تھا کہ پیچھے رہیں.مگر جب جنگ کے لئے باہر نکلنے کاحکم ہواتواس وقت وہ گھر پر موجود نہ تھے.جب وہ گھر آئے توانہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی ان کے انتظار میں بیٹھی ہے جیسے کوئی باتیں کرنے کی خواہش رکھتاہو.انہوں نے بیوی کی اس خواہش کو نظر انداز کرتے ہوئے بیوی سے پوچھا کہ کیا رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں.ان کی بیوی نے کہا کہ ذرابیٹھ توجائو.انہوں نے جواب دیا کہ خدا کارسول توجنگ کے لئے روانہ ہوجائے اورمیں گھر میں آرام کروں.ابوخثیمہ سے ایسانہیں ہوسکتا.اوراسی وقت نکل کر گھوڑے کو تیار کیااوراس پر سوار ہوکر اس راستہ پر چل پڑے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے.آخر مارامار سفر کرکے کئی منزلوں کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوگئے.جب یہ لشکر کے قریب پہنچے توبعض صحابہ نے دور سے گرد اُٹھتی ہوئی دیکھی اورخیال دوڑانے لگے کہ یہ کون آرہاہے.اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُنْ اَبَاخَیْثَمَۃُ.ابوخیثمہ ہوجا.اب اس فقرہ کا یہ مطلب توہونہیں سکتا.کہ آنے والاکوئی بھی ہو وہ ابوخیثمہ بن جائے پس اس کے معنے یہی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ آنے والا ابوخیثمہ ہو (تاریخ الطبری احداث سنہ ۹ ذکر الخبر عن غزوۃتبوک) کُنْ کے یہی معنے اس آیت میں ہیں اورمطلب آیت کا یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی امر وقوع میں آ ئے توہم خواہش کرتے ہیں کہ وہ امر اس طرح ظہور میں آجائے اورہمارے اس اراد ہ کے بعد اسی طرح ظہور میں آجاتاہے پس اس جگہ کسی معدوم شے کو حکم دینے کاسوال ہی نہیں.کُن کالفظ صرف آئندہ وقوع کی خواہش پر دلالت کرتا ہے.آیت کا مطلب غرض اس آیت کاصر ف یہ مطلب ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی امر ہوجائے توہم اس قسم کی چیز کے پیداکرنے کاارادہ کرلیتے ہیں اورجس طرح ہم ارادہ کرتے ہیں اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے.وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ اورجن لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیاگیا اللہ (تعالیٰ)کے لئے ہجرت اختیار کی(ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً١ؕ وَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ١ۘ لَوْ كَانُوْا کہ)ہم انہیں ضرورہی دنیا میں اچھی جگہ دیں گے.اورآخرت کااجر (تو)اوربھی بڑاہوگا.کاش یہ (منکر اس
Page 89
يَعْلَمُوْنَۙ۰۰۴۲ حقیقت کو)جانتے.حَلّ لُغَات.لَنُبَوّئَنَّھُمْلَنُبَوِّئَنَّھُمْ بَوَّأَ سے مضارع متکلم کاصیغہ ہے اوربَوَّأَہٗ اور بَوَّأَ لَہٗ مَنْزِلًا کے معنے ہیں:ھَیَّاَ ہُ ومَکَّنَ لَہُ فیْہِ.اس نے اس کے رہنے کے لئے مکان تیارکیا (اقرب)پس لَنُبَوِّئَنَّھُمْ کے معنے ہوئے.ہم ضروران کے لئے جگہ بنائیں گے.تفسیر.اس رکوع میں پچھلی آیت کُنْ فَیَکُوْنُ کاثبوت دیا ہے کہ دیکھ لو تھوڑی سی جماعت ہے تم نے ان پر ایسے ظلم کئے ہیں کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا.پس ایسے لوگوںکوہم دنیا میں اچھی سے اچھی جگہ دیں گے اوریہ ہوکررہے گا.فِي اللّٰهِ میں لفظ فِی کے تین معانی فِي اللّٰهِاس کے معنے کئی طرح ہوسکتے ہیں (۱)فِی بمعنی لام ہو.اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی خاطرہجرت کی.اس کے سواکوئی اورمقصدان کا نہ تھا.حدیث میں آیا ہے کہ ہجرتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں.کوئی انسان بیوی کی خاطر ہجرت کرتا ہے کوئی مال کی خاطر.کوئی خدا کی خاطر(بخاری کتاب بدءالوحی باب کیف کان بدء الوحی الیٰ رسول اللہ ).توفرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جوصرف خدا تعالیٰ کی خاطرہجرت کررہے ہیں.آج دشمن اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے روپے کی خاطرلڑائیاں کیں.عالم الغیب خداجوجانتاتھا کہ ایسے اعتراض اس کے پاک بندوں پرکئے جائیں گے اس نے لڑائیوں کے شروع ہونے سے بھی پہلے اس اعتراض کا جواب دے دیا.(۲)اس میں مضاف کو مقدر سمجھاجائے اورعبارت یوں سمجھی جائے فِی دِیْنِ اللہِ یعنی وہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرتے ہیں.یعنی ان کی ہجرت اس غرض سے ہے کہ مکہ میں تودین کاکام کرنے کی آزادی نہیں.پس ترک وطن کرکے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں دین کی خدمت کرنے کی آزادی ہو.(۳) فِیْ کے وہی معنے لئے جائیں جو زیاد ہ معرو ف ہیں.اس صورت میں ان الفاظ کا یہ مطلب ہوگاکہ انہوں نے اللہ میں ہوکر ہجرت کی.یعنی کلی طورپر اللہ تعالیٰ کو اپنے پر مستولی کرلیا.اوراس کی صفات کو اختیار کرلیا اوراپنے نفس کو مارکر اپنے ہر اک کام کوخدا تعالیٰ کے لئے کردیا.پس گویا ان کامکہ سے نکلنا چند انسانوں کا نکلنانہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کامکہ سے نکل جاناتھا.ا ن کے جانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بھی مکہ والوں کے ہاتھ سے نکل گیا.
Page 90
مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُوْایعنی ان کی ہجرت بغیر کسی وجہ کے نہیں.بلکہ اس لئے ہے کہ لوگوں نے ان کو وہاں رہنے نہیں دیااورنکلنے پرمجبورکردیا.مومن کو کفار کے ظلم کے باعث جلد ی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے اس آیت سے استدلال ہوتاہے کہ مومن کوجلدی ہی اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے.بلکہ تبلیغ کر تے رہنا چاہیے جب تک کہ لوگ اس حد تک مجبورنہ کردیں کہ دین پر عمل وہاں ناممکن ہوجائے.لَنُبَوِّئَنَّهُمْکے وعدہ کے مطابق صحابہ کی عزت لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ضرورہی ہم ان کو اسی دنیا میں اس سے بہتر مقام دیں گے چنانچہ اس کے مطابق جہاں بھی مسلما ن گئے وہیں ان کو بہتر مقام ملا.یہ ذکر اس ہجرت کا ہے جو مدینہ کی طرف حضرت عمرؓ اوربعض اورصحابہؓ نے کی تھی.مگر اس سے پہلے یا اس کے بعد جدھر بھی مسلمانوں نے ہجرت کی وہ جگہ ان کے لئے بہتر ہوگئی.اگرہجرت کے آخری انجا م کودیکھاجائے تواس ہجرت کے نتیجہ میں معمولی تاجر اوراونٹ پالنے والے دنیا کے بادشا ہ ہوگئے.وَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُیعنی اصل مقام توجزا ء کابعد الموت آئے گا اور وہ انعام بہت بڑاہوگا.مگر ان لوگوں کو سمجھا نے کے لئے دنیا میں بھی ہم مسلمانوںکو اعلیٰ مقام عطافرمائیں گے.وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُکے معنے اس مقام سے جو حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کو دنیا میں ملا خو ب سمجھ میں آسکتے ہیں.ان کو خدا تعالیٰ نے متمدن دنیا کے اکثر حصہ پر حکومت دی.جب انعام کا یہ حقیر حصہ تھاتوبڑاحصہ کیاہوگااورہراک صحابی کیا اجر پارہاہوگا.اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے یہ ہے کہ اس میں بتایاتھا کہ تم قیامت کے منکر اس لئے ہو کہ ایسا ہوناناممکن ہے لیکن دیکھتے نہیں کہ کس طرح ہم اس دنیا میں حکم دیتے ہیں اورناممکن باتیں ممکن ہوجاتی ہیں.پھر بعث بعدالموت کو تم ہمارے لئے کیو ں ناممکن خیال کرتے ہو.اب اس دعویٰ کی تائید میں ایک پیشگوئی فرماتا ہے جویہ ہے کہ مکہ والے تو مسلمانوں کوذلیل سمجھتے ہیں اوران کو تکلیف دے کر اس لئے وطن سے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ باہر جاکر بے گھر بے درہوجائیں اورتکلیف پائیں.مگرہم پیشگوئی کرتے ہیں کہ ان کا باہر نکلنا مفید ہوجائے گااوراس ہجرت کے نتیجہ میں ان کو دینی ہی نہیں بلکہ دنیوی فوائد بھی پہنچیں گے اورانہیں حکومت مل جائے گی.یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھے.اورمسلمان ایسے کمزو ر تھے کہ مکہ والے آپ کو قتل کرنے یاگھر سے نکال دینے یاقید کرنے کے منصوبے کررہے تھے.اس کے ایک دوسال کے اندر اس ہجرت کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوبادشاہ بنا دیا.یہ ایک زبردست نشان ہے ان لوگوں کے لئے جو قیامت کا انکار اس
Page 91
لئے کرتے ہیں کہ ایسی بات کس طرح ہوسکتی ہے.جوخداعجائبات دکھانے کاعادی ہے اس کی کس قدر ت پر انسان تعجب کرسکتا ہے.الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ۰۰۴۳ جو (ظلموں کا نشانہ بن کر بھی )ثابت قد م رہے اور(جوہمیشہ ہی )اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں حَلّ لُغَات.صَبَرُوْا.صَبَرُوْا صَبَرَ سے جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.صَبَرَ کی تشریح کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر۲۳.صَبَرُوْاصَبَرَ سے جمع کا صیغہ ہے اور الصَّبْرُکے معنے ہیں تَرْکُ الشِّکْوٰی مِنْ اَلَمِ الْبَلْوٰی لِغَیْرِاللہِ لَا اِلَی اللہِ کہ مصیبت کے دکھ کا شکویٰ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کےپاس نہ کرنا.فَاِذَا دَعَا اللہَ الْعَبْدُ فِیْ کَشَفِ الضُّرِّ عَنْہُ لَا یُقْدَحُ فِیْ صَبْرِہِ.اگر بندہ اپنی رفع مصیبت کے لئے خدا تعالیٰ کے پاس فریاد کرے تو اس کے صبر پر اعتراض نہ کیا جائے گا.وَقَالَ فِی الْکُلْیَاتِ الصَّبْرُ فِی الْمُصِیْبَۃِ.اور کلیات میں لکھا ہے کہ صبر مصیبت کے وقت ہوتا ہے.وَصَبَرَ الرَّجُلُ عَلَی الْاَمْرِ نَقِیْضُ جَزِعَ اَیْ جَرُؤَ وَشَجُعَ وَتَجَلَّدَ اور صبر جزع یعنی شکویٰ کرنے اور گھبرانے کے مقابل کا لفظ ہے اور صَبَرَ کے معنے ہوتے ہیں دلیری دکھائی.جرأت دکھائی.ہمت دکھائی.اور صَبَرَ عَنِ الشَّیْءِ کے معنے ہیں اَمْسَکَ عَنْہُ کسی چیز سے رکا رہا.اَلدَّابَۃَ حَبَسَہَا بِلَاعَلَفٍ.اور صبر کا مفعول دابّۃ ہو تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ جانور کو بغیر چارہ دینے کے روکے رکھا.صَبَرْتُ نَفْسِیْ عَلٰی کَذَا کے معنے ہیں میں نے اپنے نفس کو کسی چیز پر قائم رکھا یا کسی چیز سے روکے رکھا.چنانچہ انہی معنوں میں صَبَرْتُ عَلٰی مَااَکْرَہُ وَصَبَرْتُ عَمَّا اُحِبُّ کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ تکلیف دہ حالت پر میں نے نفس کو استقلال سے قائم رکھا اور پسندیدہ امور سے نفس کو باز رکھا گویا صبر کے تین معنے ہوئے گناہ سے بچنا اور اپنے نفس کو اس سے روکے رکھنا.(۲)نیک اعمال پر استقلال سے قائم رہنا.(۳)جزع فزع سے بچنا.(اقرب) یَتَوَکَّلُوْنَ یَتَوَکَّلُوْنَ تَوَکَّل سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۶۸.تَوَکّلَ عَلَی اللہِ : اِسْتَسْلَمَ اِلَیْہِ وَاعْتَمَدَ وَوَثِقَ بِہِ توکل علی اللہ کے معنی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے
Page 92
سپرد کردیا اور اسی پر بھروسہ و اعتماد کیا.(اقرب) تفسیر.مراد یہ ہے کہ ھَاجَرُوْا اورظُلِمُوْا جن لوگوں کی نسبت ہم نے کہاہے وہ ایسی جماعت ہے کہ اس پر ظلم ہوئے اورانہوں نے صبر کیا اورگھروں سے بے گھر کئے گئے مگراللہ تعالیٰ پر امید نہ چھو ڑی.آنحضرت ؐ کی ترقی کے متعلق کفار کے خیالات کی تردید اس آیت میں پہلی دوصفات کی گویا مزید تشریح کی گئی ہے مظلوم ہونا خدا تعالیٰ کی مدد کو کھینچتاہے.مگرجو مظلوم بھی ہواورپھر صبر بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو بہت زیادہ اوربہت جلدی جذب کرتا ہے.اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خاطرتکلیف اٹھا کرہجرت کرناایک بڑی نیکی ہے.مگر اس حالت میں جب کہ سب سامان لٹ جائے اوروطن تک چھوڑنا پڑے دل کو اس یقین سے پُررکھنا کہ ہم تباہ نہیں ہوسکتے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کر ےگا اس سے بھی بڑی نیکی ہے.وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ اورہم تجھ سے پہلے (بھی ہمیشہ)مردوں ہی کو رسول بناکر بھیجا کرتے تھے ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ اور(اے منکرو)اگرتم (اس حقیقت کو )نہیں جانتے تواس(اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے )ذکر(کوماننے )والوں لَا تَعْلَمُوْنَۙ۰۰۴۴ سے (ہی) پوچھ(کرمعلوم کر)لو.حَلّ لُغَات.الذّکر.اَلذّکْرُ کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۱۰۵.اَلذِّکْرُ: التَّلفُّظُ بِالشَّیْءِ وَاِحْضَارُہُ فِی الذِّھْنِ بِحَیْثُ لَایَغِیْبُ عَنْہُ.کسی چیز کا منہ سے ذکر کرنا اور اسے ایسے طور پر مستحضر فی الذہن کرنا کہ وہ بھول نہ جائے.اَلصِّیْتُ وَمِنْہُ لَہٗ ذِکْرٌ فِی النَّاسِ.شہرت اور انہی معنوں میں لَہُ ذِکْرٌ فِی النَّاسِ کا فقرہ بولتے ہیں کہ فلاں شخص کو لوگوں میں شہرت حاصل ہے.تفسیر.یعنی ان لوگوں کی مخالفت کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدعی ہمارے جیسا آدمی ہے اس لئے ہمار اکیا بگاڑ سکتا ہے.لیکن یہ نہیں جانتے کہ پہلے نبی بھی توانسانوں جیسے انسان تھے پھر وہ کس طرح
Page 93
کامیاب ہوگئے.فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ کہہ کر کفار کو شرمندہ کیا گیا فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ کہہ کر کفار کو شرمند ہ کیا گیا ہے.وہ دعویدا ر تھے کہ وہ ابراہیم ؑ اوراسمٰعیل ؑ کی اولاد ہیں (سیرۃ النبی لابن ہشام سیاقة النسب ولد اسماعیل علیہ السلام )اوران کے حالات بھی ان کے سامنے تھے کہ کس طرح تکالیف اٹھا کرکامیاب ہوئے.پس فرماتا ہے کہ تم توشائد اپنے بزرگوںکو بھول گئے ہو.اگر تم کو ان باتوںکاعلم نہیں تودوسری اقوام سے دریافت کرلو.اہل ذکر کے معنی یاد رکھنے والے کے ذکر کے معنے چونکہ یاد رکھنے کے بھی ہیں.اہل الذکر سے مراد یاد رکھنے والے کے بھی ہوسکتے ہیں.اس صورت میں یوں معنے ہوں گے کہ اگرتم نہیں جانتے اورباپ دادوں کی باتوں کو بھو ل گئے ہو توجن کو یاد ہیں ان سے پوچھ لو یعنی مسلمانوں سے.یہ پیرایہ کلام نہایت لطیف اوربلیغ ہے.کفاریہ طنز سن کر دل میں کٹ ہی مرے ہوں گے.نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ کہہ کرا س طر ف اشارہ کیاگیا ہے کہ نبی کا شرف فوجوںاورسامانوں سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی دولت اس کی وحی ہوتی ہے اوراس کے ذریعہ سے وہ فتح پاتا ہے.ا س آیت میں ا س طرف بھی اشارہ ہے کہ اگرکفار خیا ل کریں کہ اس بے سامان آدمی کے ذریعہ سے مسلمانوں کوحکومت کہاں سے مل جائے گی توان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے انبیاء بھی ایسے ہی تھے اوران کے پاس وحی الٰہی کے سوااور کچھ نہ تھا.پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے دنیا میں بہت بڑے تغیرات پیداکردیئے اوراسی دنیا میں ایک حشر برپاکردیا.رِجَالًا کہے جانے کی وجہ یہاں پر رِجَالًا اس لئے فرمایا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے پر ملائکہ کیوں نازل نہیں ہوتے.چنانچہ پہلی سورۃ میں بھی ان کا مطالبہ لَوْ مَاتَأتِیْنَا بِالْمَلٰئِکَۃِ کے الفاظ میں گذر چکا ہے.یہاں ان کے اس خیال کو مدنظر رکھ کر ایک طنز بھی کی ہے.اوروہ یہ کہ تم تو فرشتوں کوخدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہو پھر وہ ایلچی بن کر تمہارے پاس کیونکر آئیں.ایلچی بن کر تومرد ہی آئیں گے.چونکہ ہجرت کے بعد حکومت ملنی تھی اورحکومت کے ساتھ ان لالچیوں کے گروہ نے بھی پیداہوناتھا جواس حکومت کو دنیو ی حکومت سمجھ کر اس میں سے حصہ بٹانے کی کوشش کرنے والے تھے جیسے کہ مسیلمہ سجاح وغیر ہ نے.اس لئے کوئی بعید نہیں کہ اس آیت میں اس آنےوالے فتنہ کابھی سدباب کیا گیا ہو کہ جب لو گوں نے فصاحت پر دعویٰ نبوت کی بنیاد رکھنی تھی اوربعض عورتیں بھی نبوت کادعویٰ کرنے والی تھیں ان دونوں خیالا ت کارد رِجَالًا اور
Page 94
نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ کے الفاظ سے کیاگیا.بِالْبَيِّنٰتِ وَ الزُّبُرِ١ؕ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ (ہم نے انہیں)روشن نشانات اور(الہامی)نوشتے دےکر (بھیجاتھا )اورتجھ پر ہم نے یہ (کامل)ذکر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ تاکہ تُو سب لوگوںکو وہ(فرمان الٰہی )جو(تیرے ذریعہ سے )ان کی طرف نازل کیاگیا ہے کھول کربتائے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۰۰۴۵ اورتاکہ وہ (اس پر )تدبرکریں.حَلّ لُغَات.بِالْبَیِّنٰتِ.اَلْبَیِّنَاتُ اَلْبَیِّنَۃُ کی جمع ہے.اوراَلْبَیِّنَۃُ کے معنے ہیں.اَلدَّلِیْلُ اَلْحُجّۃُ.دلیل(اقرب) الزُّبُر زَبَرہٗ( یَزْبُرُ) زَبْرًا کے معنے ہیں :رَمَاہُ بِالْحِجَارَۃِ.اس کو پتھر مارے.زَبَرالْکِتَابَ (یَزْبِرُ.یَزْبُرُ):کَتَبَہٗ.کتاب کولکھا.وَزَادَ فی مُفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ کِتَابَۃً غَلِیْظَۃً.اورمفردات میں زَبَرَکے معنے موٹی قلم یا گہری روشنائی سے لکھنے کےآئے ہیں.زَبَرَالسَّائِلَ:اِنْتَھَرَہٗ.سائل کوڈانٹا.زَبَرَعَنِ الْاَمْرِ:مَنَعَہٗ وَنَھَاہٗ.کسی کام سے روکا.اَلزِّبْرُ کے معنے ہیں.اَلْکِتَابُ.کتاب.اس کی جمع زُبُوْرٌ ہے اور الزَّبُوْرُ کے معنے ہیں اَلْفِرْقَۃُ.حصہ.الْمِلْکُ.ملک.اَلْکِتَابُ.کتاب.کیونکہ یہ بھی لکھی جاتی ہے.اس کی جمع زُبُرٌ ہے (اقرب) تفسیر.اس آیت میں پہلے مضمون کی مزید تشریح اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح کی ہے اوربتایا ہے کہ نبی بیّنات اورزُبر لے کر آتے رہے ہیں.یعنی نشانات اوراحکام الٰہی لانا ہی ان کی غرض تھی اور انہی دونوں سامانوں سے ان کی ترقی ہوتی رہی ہے.اس جگہ الذّکْرَ سے مراد اعلیٰ شرف والی کتاب کے ہیں وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ کے گولفظی معنے تویہی ہیںکہ تجھ پر ہم نے ذکر اتاراہے.لیکن چونکہ یہ زُبُر کے مقابل پر ہے جس کے معنے کتاب کے ہیں یعنی اس وحی کے جس کاماننا فرض ہو.اس لئے ذکر کے معنے اس جگہ خا ص ہوجائیں گے.کیونکہ جب دو لفظ ایک دوسرے کے مقابل استعمال کئے جائیںتواگر دونوں لفظ مختلف قسم کی اشیاء پر دلالت نہ کرتے ہوںتوبعد میں آنے والا لفظ یاپہلے سے
Page 95
اعلیٰ معنے دیتا ہے یاادنیٰ.اس جگہ چو نکہ موقعہ اعلیٰ معنو ں کے اظہارکا ہے.اس لئے الذِّكْرَ کے معنے اعلیٰ شرف والی کتاب کے ہوں گے یازیادہ مکمل کتاب کے.اورمطلب یہ ہوگاکہ پہلوںکوتوبیّنات اورزُبر ملتے رہے ہیں تجھے بیّنات اورالذکر ملے ہیں جوان کے انعام سے زیادہ ہے.پس اگر تیری کتاب سے ادنیٰ درجہ کی کتب کی مددسے پہلے انبیاء اپنے دشمنوں کوشکستیں دیتے رہے ہیںتوتُو ان سے اعلیٰ الہام کامورد ہوکر کیوں اپنے دشمنوں کو شکست نہ دے سکے گا.ان معنوں کے روسے الذِّكْرَ کاالف لام کما ل کے معنوں میں لیاجائے گا.اس آیت میں ذکر کے دوسرے معنی بھی چسپاں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ذکر کے جو دوسرے معنے ہیں.وہ بھی اس سے مراد ہوسکتے ہیں.اوروہ یہ ہیں (۱)دعا(۲)محکم.مضبوط(۳)ثناء.تعریف (۴) کسی چیز کااس طرح ذہن میں رکھنا کہ وہ بھول نہ سکے.ان معنوں کے روسے آیت کے معنے ہوں گے کہ ہم نے تجھے جو کتاب دی ہے.اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ وہ کامل دعائوں پر مشتمل ہے اوراس وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کے خا ص فضل جذب کرنے کاموجب ہوگی.اورپھر وہ محکم تعلیمات پر مشتمل ہے.اس لئے کوئی اعتراض اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا.اورپھر وہ ثناء ہے جو لو گ اس سے تعلق رکھیں گے ان کی تعریف کاموجب ہوگی.ان کے اخلاق اوراعما ل کو ایسابنادے گی کہ دنیا ان کی تعریف کرے گی یایہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کامل ثناء ہے اس وجہ سے ماننے والوں کا عرفان بڑھے گا.پھر وہ ایسی مقبول ہو گی کہ اُسے بھلایانہ جائے گاہروقت لوگ اس کی تلاوت میں مشغول رہیں گے.لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ.لِتُبَيِّنَ کالام لام تعلیل بھی ہوسکتا ہے اورلام عاقبت بھی.لام تعلیل کی صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم نے تجھ پر دوسری کتب سے اعلیٰ خوبیوں والی کتاب اتاری ہے تاکہ تو سب دنیا کو وہ تعلیم سنائے جو ان کے لئے اتاری گئی ہے.یعنی تجھ پر اترنے والی تعلیم کا سب سے اعلیٰ ہونا اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی ایک قوم یاایک زمانہ کے لوگوں کے لئے نازل نہیں کیا.بلکہ سب لوگوں کے لئے نازل کیا ہے.خواہ وہ کسی قوم کے ہوں یاکسی زمانہ کے ہوں.لام عاقبت کی صورت میں یہ معنے ہوں گے کہ چونکہ تجھ پر اعلیٰ کتاب نازل ہوئی ہے اس لئے تواسے مخفی کس طرح رکھ سکتاتھا.اس اعلیٰ کتاب کانزول اس کاباعث ہواہے.کہ توسب دنیا کو اس کی طرف بلارہاہے.ایسی کتاب جس پر نازل ہو وہ خاموش کس طرح رہ سکتاہے.نُزِّلَ اِلَيْهِمْ کے الفاظ سے دو باتوں کی طرف اشارہ نُزِّلَ اِلَيْهِمْ کہہ کر کفار کے جذباتِ محبت کو ابھاراہے.یعنی گوکتاب تجھ پرنازل ہوئی ہے.لیکن چونکہ غرض یہ ہے کہ اس کتاب سے سب دنیا فائدہ اٹھائے اس
Page 96
لئے درحقیقت یہ نزول ساری دنیا پر ہی ہے.پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کی قد رکیوں نہیں کرتے.نُزِّلَ اِلَيْهِمْ سے اس امر پر بھی زوردیاگیا ہے کہ اس کتاب کاسب دنیا تک پہنچانا ضروری ہے.کیونکہ اس کا نزول سب دنیا کی طرف ہے اوریہ سب دنیا کامال ہے.پس ان تک اس کا پہنچانا نہایت اہم فرض ہے.کاش!مسلمان اس نکتہ کو سمجھتے اورتبلیغ اسلام کے فریضہ کے اداکرنے میں سستی نہ کرتے.توآج دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اورمذہب نظرنہ آتاکیونکہ اس کی پا ک تعلیم کے سامنے کوئی اورتعلیم ٹھہر ہی نہیں سکتی.آج بے شک اس کی اشاعت میں روک ہے.کیونکہ دنیوی حرص و آز اسلام کے قبول کرنے میں روک ہورہی ہے مگر یہ حالت توآج پیداہوئی ہے.پہلے تودنیا بھی مسلمانوں کے قبضہ میں تھی.جس طرح دین ان کے ہاتھ میں تھا.لِتُبَيِّنَ کے الفاظ سے قرآن کی دوسری کتب کے بالمقابل فضیلت لِتُبَيِّنَ میں ایک اورلطیف مضمون بھی بیان کیاگیا ہے اوروہ یہ ہے کہ بعض کتب ایسی ہیں جن کو انسان شرم کی وجہ سے سنا ہی نہیں سکتا.مثلاً بائبل کے بعض ٹکڑے.لیکن قرآن کریم ایسی شریفانہ باتوں پر مشتمل ہے کہ ہر جگہ پر اُسے سنایاجاسکتاہے.ایک عیسائی کاقول ہے کہ قرآن میں یہ خوبی ہے کہ ہرمجلس میں پڑھاجاسکتاہے.مگر ہماری کتابیں ایسی ہیں کہ ہرمجلس میں نہیں پڑھی جاسکتیں.حضرت لوط اوران کی لڑکیوں کاواقعہ.بنی اسرائیل کاعورتوں بچوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے قتل کرنا یہ ایسے واقعات ہیں کہ ان کامجالس میں بیان کرنا طبیعت پر سخت گراں گذرتا ہے(پیدائش باب ۱۹ آیت ۳۱،۳۸ واستثناء باب ۳ آیت ۶).آریہ لوگوں کی نیوگ کی تعلیم بھی ایسی ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ توالگ رہے خود آریہ خاوند اپنی بیوی کو وہ تعلیم پڑ ھ کر نہیں سناسکتا.مگرقرآن کریم ایسے مضامین پر مشتمل ہے اورایسے الفاظ میںبیان ہواہے کہ اسے ہرقوم پر اورہرعمر کے لوگوں کے سامنے پڑھاجاسکتاہے.الہام فکر انسانی کو تیز کر دیتا ہے.لَعَلَّہُمْ یَتَفَکَّرُوْنَ سے اس طر ف اشارہ کیا گیا کہ الہام فکر انسانی کو تیزکردیتا ہے.صحابہ کانمونہ اس کابیّن ثبوت ہے.وہ اَن پڑھ اورزمانہ کے حالات سے ناواقف تھے.مگرالہام قرآنی کو سن کر اورسمجھ کر دنیا کے علماء کے استاد بن گئے اورایسی سمجھ ان کو عطاہوئی کہ دنیا کے ہر علم میں انہوںنے آئندہ زمانہ کے لئے ایک بہترین سبق چھوڑاہے.
Page 97
اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَکَرُواالسَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ پھرکیاجولوگ(تیرے خلاف )بری (بر ی) تدبیریں کرتے چلے آئے ہیں وہ اس بات سے امن میں ہیں کہ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ اللہ (تعالیٰ)انہیں اس ملک میں(ہی)ذلیل (و رسوا)کردے یاوہ عذاب (جس کی خبر دی جاچکی ہے ) لَا يَشْعُرُوْنَۙ۰۰۴۶ جہاں سے وہ جانتے (بھی)نہ ہو ں اُ ن پر آجائے.حلّ لُغَات.یخسف یَخْسِفُ خَسَفَ سے مضارع واحد مذکر غائب کاصیغہ ہے اورخَسَفَ الْمَکَانُ خُسُوْفًاکے معنے ہیں :ذَھَبَ فِی الْاَرْضِ وَغَرِقَ.کوئی جگہ زمین کے اند ر دھنس گئی.خَسَفَ اللہُ تَعَالٰی الْاَرْضَ:اَسَاخَھَابِمَا عَلَیْھَا.اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو زمین سمیت غرق کردیا.خَسَف اللہُ الْاَرْضَ بِفُلَانٍ:غیَّبَہُ فِیْھَا.اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں غائب کردیا.خَسَفَ فِی الْاَرْضِ وَخُسِفَ بِہِ مَجْھُوْلًااَیْ غَابَ فِیْھَا زمین میں دھنس کر غائب ہو گیا.خَسَفَ فُلَانًا.(بغیر صلہ کے)اَذَلَّہُ وَحَمَّلَہُ مَایُکْرَھُہُ.ا س کو ذلیل کیا اوراس پر ایسے معاملات ڈالے جن کو وہ ناپسند کرتاتھا (اقرب) پس یخسفُ بِھم کے معنے ہوں گے کہ (۱)ان کو زمین میں دھنسادے (۲)ان کو زمین کے اندر غائب کردے (اقرب) تفسیر.آیت اَنْ يَّخْسِفَ میں کفار کے انجام کی پیشگوئی اس آیت میں ایک اورپیشگوئی بیان کی گئی ہے جوکفار کے انجا م کے متعلق ہے.فرماتا ہے کیاکافراس سے مامون ہوگئے ہیں.کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کےاندر دھنسادے.خسف کے معنی گمنام ہونے کے خسف کے معنے دھنسانے کے بھی ہیں اورذلیل کرنے کے بھی.مگرجب ذلیل کرنے کے معنوں میں آئے تواس وقت اس کا مفعول بغیر کسی صلہ کے آتاہے جیسے کہ خَسَفَ فُلَانًا اورجب باء کاصلہ آئے توا س کے معنے دھنسادینے کے یااندرغائب کرنے کے ہوتے ہیں.جیسے کہتے ہیں خَسَفَ الْاَرْضَ بِفُلَانٍ فلاں شخص کو زمین میں غائب کر دیا.چونکہ اس آیت میں باء کاصلہ استعمال ہواہے اس لئے یہی معنے اس کے ہوسکتے ہیں کہ ان کو زمین کے اندر غائب کر دے یا دھنسادے.لیکن مرادگمنام ہوجانے اورجیتے جی
Page 98
دفن ہوجانے کے ہوںگے اوراستعمال مجازی سمجھا جائے گا.کفار پر موعود عذاب کا ظہور اور صحابہ کی عزت یہ عذاب کفار پر اس شان کے ساتھ آیا کہ آج صنادید عرب کے ناموں اوران کے خاندانوںکو کوئی جانتا بھی نہیں.لیکن ابو بکرؓ، عمر ؓ، عثمانؓ، علی ؓاوران کی نسلوںکو آج بھی لوگ سر پربٹھاتے ہیں.پیشگوئی کے مطابق فتح مکہ کے وقت کفار پر اچانک عذاب کا نزول اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ گو ہرعذاب ہی اسی طر ح آتا ہے کہ کفار جانتے نہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض واقعات اس آیت پر حیرت انگیز طور پر چسپاں ہوتے ہیں.مثلاً صلح حدیبیہ کاواقعہ ہی لے لو اس صلح کے وقت مکہ والوں کاخیال تھا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی فتح حاصل کی ہے لیکن اس کے بعد جس طرح حالات نے یکدم پلٹاکھایا وہ ایک زبردست نشان ہے.پہلے مکہ والوں نے اس شرط کے پوراکرنے پر اصرارکرکے کہ جو ہم میں سے اسلام لاکر مدینہ جائے اسے واپس کردیاجائے مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت پیداکردی جورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے آزاد ہوکر مکہ والوں سے برسرپیکار ہوگئی.اورآخر مکہ والوں کو ذلیل ہو کرآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنی پڑی کہ اس جماعت کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی جائے.اس کے بعد خود کفار کی باہمی لڑائی نے معاہدہ کے روسے مسلمانوں کو مکہ پرچڑھائی کاحق دےدیا.اوراس طرح مکہ اچانک اوریکدم فتح ہوگیا.(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام امر الھدنة) اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَۙ۰۰۴۷ یاوہ انہیں (قومی معاملات میں )ان کے آزادانہ تصر ف کی حالت میں ہلاک کردے پس (وہ یاد رکھیں کہ)وہ (ہرگز اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کے پوراکرنے سے )عاجز نہ پائیں گے.حَلّ لُغَات.تَقَلُّبھمْ: تَقَلَّبَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں تَـحَوَّلَ عَنْ وَجْھِہِ.اپنی جہت سے پھر گیا تَقَلَّبَ عَلٰی فَرَاشِہِ:تَحَوَّلَ مِنْ جَانِبٍ اِلٰی جَانِبٍ.بستر پر کروٹیں لیتارہا.تَقَلَّبَ فِی الْاُمُوْرِ:تَصَرَّفَ فِیْھَا کَیْفَ شَآءَ.یعنی جس طرح چاہا اپنے معاملات میں خود مختاری سے کام لیا.(اقرب) مُعْجِزیْنَمُعْجِزِیْنَ اَعْـجَزَ سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے.اوراَعْـجَزَہُ الشَّیْءُ کے معنے ہیں فَاتَہٗ.وہ چیز
Page 99
اس کے ہاتھ سے جاتی رہی.اَعْـجَزَ فُلَانٌ فُلَانًا :صَیَّرَہٗ عَاجِزًا فلاں نے فلاں کو عاجز کر دیا.اَعْـجَزَہُ : وَجَدَہُ عَاجِزًا.اس کو عاجز پایا (اقرب)پس فَمَاھُمْ بِمُعْجِزِیْنَ کے معنی ہوں گے وہ اس کو عاجز نہیں پائیں گے وہ اس کوعاجز نہیں کرسکیں گے.تفسیر.تَقَلُّب کے معنی تَقَلُّب کے معنے سفر کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ فرمایا ہے لَایَغُرَّنَّکَ تَقَلُّبُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْافِی الْبِلَادِ (آل عمران :۱۹۷)یعنی کفار کاادھر ادھر اموال تجارت لے کر پھر نا تجھے دھوکہ میں نہ ڈالے اورتجھے یہ خیال نہ ہو کہ ان کے پاس تو بڑاسرمایہ ہے.بڑی طاقت ہے یہ کس طرح مغلوب ہوں گے.ان معنوں کے روسے آیت زیر بحث کے معنے یہ ہوں گے کہ کفار مطمئن نہ ہوں کہ ان کے سفر ان کی طاقت کا موجب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان سفروں میں ہی عذاب میں مبتلاکرے گا.چنانچہ غزوہ بدر ایک قافلہ کی حفاظت ہی کی غرض سے ہوااوراس میں کفار مکہ کی شوکت جاتی رہی.دوسرے معنے تقلّب کے تصرف کے ہیں.ان معنوں کے روسے آیت کے معنے ہوں گے کہ ان کے تصرف میں خلل آجائے گااورحکومت ضعیف ہوجائے گی چنانچہ یہ عذاب بھی مکہ والوں پر صلح حدیبیہ کے موقعہ پر نازل ہوااوربعض کافر قبائل نے مکہ والوں کے جتھا میں شامل ہونے سے انکار کردیا اورفیصلہ کیا کہ باوجود مذہبی اختلا ف کے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اوریہی قبیلہ مکہ پر حملہ کروانے کاموجب بنا (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام غزوة بدر القبری).اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ١ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ یاوہ انہیں آہستہ آہستہ گھٹاکر ہلاک کردے.کیونکہ تمہارارب یقیناً(مومنوںپر )بہت(ہی ) لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۰۰۴۸ شفقت کرنے والا (اور)باربار رحم کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.تَخوُّفٍ:تَخَوَّفَ عَلَیْہِ شَیْئًاتَخَوُّفًا:خَافَہُ عَلَیْہ.اس پر کسی مصیبت کے آنے کا خوف محسوس کیا.وَتَخَوَّفَ الشَّیْءَ :تَنَقَّصَہٗ.کسی چیز کو تھوڑاتھوڑاکرکے لیا.تَخوَّف حَقَّہُ:تَھَضَّمَہٗ اِیّاہٗ.اس کے حق کو مار لیا.ھُوَیَأخُذَھُمْ عَلی تَخَوُّفٍ.اَیْ یُصَابُونَ فِیْ اَطْرَافِ قُرَاھِمْ بِالشَّرِّ حَتَّی یَأْتِیَ ذَالِکَ عَلَیْہِمْ.ھُويَاْخُذُهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍکے معنے ہیں کہ ان کی ارد گرد کی بستیو ںپر تکالیف آرہی ہیں.یہاںتک کہ اب ان کی
Page 100
نوبت بھی آرہی ہے.(اقرب)وَالتَّخَوُّفُ: ظُہُوْرُالْخَوْفِ مِنَ الْاِنْسَانِ.انسان سے کسی خوف اورڈر کے ظاہر ہونے کانام تخوّف ہے (مفردات) تفسیر.يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ کے دو معنی یعنی ایک اوررنگ کاعذاب بھی مکہ والوں کو ملے گااوروہ یہ کہ مکہ والوں کے تابع جو علاقے ہیں وہ آہستہ آہستہ انہیں چھوڑتے جائیں گے.چنانچہ مختلف علاقو ں کے لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی اسلام لاناشروع کردیاتھا.اس آیت کے یہ معنے بھی ہیں کہ ایک عذاب تم پر خوف کاآئے گایعنی باوجود زیادہ ہونے کے تمہارے دلوں پر مسلمانوں کا ایسارعب بٹھادیاجائے گاکہ تم اند ر ہی اند رخوف سے مرتے جائو گے.اس قسم کا عذاب نہایت شدیدہوتا ہے کیونکہ ا س کااثر اعصاب پر پڑ کر انسان کی حالت سخت پریشانی کی ہوجاتی ہے.یہ عذاب بھی مکہ والوں پر نازل ہوا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اورصحابہؓ کارعب ان پر ایساتھا کہ ہر وقت وہ اسی غم میں گھُلے جاتے تھے.حدیث میں آتاہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ (بخاری کتاب الصلٰوۃ باب قول النبی ؐ جعلت لی الارض مسجدا) اللہ تعالیٰ نے میری مدد رعب کے قیام سے بھی کی ہے جدھر میں نکلو ں مہینہ بھر کی مسافت کے علاقہ تک لوگوں میں دہشت پھیل جاتی ہے.سزا کے بعد صفت رؤوف کے ذکر کی وجہ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.یہ عجیب بات ہے کہ سزاکے ذکر کے بعد رءو ف ہونے کا ذکر کیاہے.اس کی وجہ اول تویہ ہے کہ یہ سارے عذاب تدریجی آئے ہیں.پہلے تخوف سے ان کو سمجھا یا یعنی ادھر ادھر بستیوں میں اسلام پھیلایا.پھر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں.پھر صلح حدیبیہ ہوئی جس سے ان کا رعب اڑ گیا.پھر اچانک فتح مکہ کے وقت ان کو شہر میں جاپکڑا.پس یہ رأفت اوررحم ہی تھا کہ آہستہ آہستہ پکڑاتاکہ جو ہدایت کے قابل تھے ہدایت پا جائیں.ورنہ چاہتا تویکد م عذاب میں مبتلاکردیتا.عذاب کفار کے لئے ہے اور رأفت مومنوں کے لیے دوسری وجہ اس کی یہ ہوسکتی ہے اور میرے نزدیک یہی زیادہ درست ہے کہ رءو فٌ رَّحِیْمٌ مسلمانوں کے لئے آیا ہے اورمطلب یہ ہے کہ ان لوگوں پر عذاب لانا مسلمانوں پر رأفت اوررحم کی غرض سے ہوگا تاانہیں ان عذابوں اورظلموں سے بچایا جائے جو مکہ والوں کی طرف سے ان پر وار دہوتے رہتے ہیں.اس کاثبوت یہ ہے کہ جہاں عذابوں کا ذکر تھا وہاں غائب کی ضمیریں استعمال کی گئی تھیں اوررء وف رحیم سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّ رَبَّھُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.بلکہ فرمایا ہے اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.پس غائب سے خطاب کی ضمیرکو بد ل دینابتاتا ہے کہ عذاب کفار کے لئے ہوگا اوررأفت اوررحمت مومنوں کے لئے
Page 101
ہوں گی.اَوَ لَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ اور کیا باوجود اس کے کہ وہ ذلیل ہورہے ہیں انہوں نے (کبھی)اللہ(تعالیٰ)کے حضور(تذلّل کے ساتھ )جھکتے عَنِ الْيَمِيْنِ وَ الشَّمَآىِٕلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ ہوئے جوکچھ بھی اللہ (تعالیٰ) نے (ان کے لئے )پیدا کیا ہے اُسے غور سے نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں وَ هُمْ دٰخِرُوْنَ۰۰۴۹ جانب سے اورشمالی جانبوں سے اِدھر اُدھر ہورہے ہیں.حلّ لُغَات.یَتَفَیَّؤُایَتَفَیَّؤُا تَفیَّأَ سے مضارع مذکر غائب کاصیغہ ہے اورتَفَیَّأَتِ الظِّلَالُ کے معنے ہیں: تَقَلَّبَتْ.سائے ادھر سے اُدھر ہوگئے.(اقرب) دَاخِرُونَ دَاخِرُوْنَ دَاخِرٌ سے جمع کاصیغہ ہے اوردَاخِرٌ دَخَرَ وَدَخِرَ سے اسم فاعل ہے اوردَخَرَ کے معنے ہیں : ذَلَّ وَصَغُر ذلیل اورچھوٹاہوگیا.وَفِی الْقُرْآنِ ’’سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ‘‘ اَیْ اَذِلَّاءَ مُھَانِیْنَ.اور قرآن مجید کی آیت ’’سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ‘‘ میں داخرین کے معنے ذلیل کے ہیں.یعنی وہ ذلیل ہوکرجہنم میں داخل ہوں گے.(اقرب) تفسیر.مختلف اشیاء کے زوال سے کفار کو انتباہ اس آیت میں کفار کو توجہ دلائی ہے کہ کیاتم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اوردلوں میں خشوع پیداکر تے ہوئے خدا تعالیٰ کے قانون پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح ہرشے پرایک دن زوال آتا ہے.ہرقوم ایک دن ختم ہوجاتی ہے شہر اجڑ جاتے ہیں.حکومتیں بدل جاتی ہیں.ملک تباہ ہوجاتے ہیں.امیر غریب اورغریب امیرہوجاتے ہیں.غرض ہرچیز کاسایہ ایک وقت آکر سمٹ جاتاہے یعنی اُسے جورتبہ اوردرجہ اوراثراورنفوذ یارعب یاشوکت یاشہرت حاصل ہوتی ہے جاتی رہتی ہے.پھر اس عام قانون سے تم کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے.اورغرور اورتکبر کو چھو ڑکر حقیقت پر غورنہیں کرتے تاتم کو عبرت حاصل ہو اور تم سچائی کو قبول کرلو.
Page 102
یمین کے لفظ کے مفرد رکھے جانے اور شمائل کے جمع رکھے جانے کی وجہ میں نے جو معنے کئے ہیں ان کے مطابق سُجَّدًا لِّلّٰهِ اورهُمْ دٰخِرُوْنَ کو اَوَلَمْ یَرَوْا کی ضمیر کاحال بنایاہے.بعض لوگوں نے ان کو مَا کاحال بنایا ہے (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا).مگرچونکہ یہاں ذوی العقول کاصیغہ اورضمیر استعمال کے گئے ہیں.اس لئے میرے نزدیک وہی معنے زیادہ درست ہیں جو میں نے کئے ہیں.ایک اوربات اس آیت میں قابل حل ہے اوروہ یہ کہ یمین کالفظ مفرد ہے اورشمائل کاجمع ہے.ایساکیوں کیاگیا ہے.حالانکہ چاہیے تھا کہ یادونوں کوجمع رکھاجاتا یادونوں کو مفرد.بعض نے اس کایہ جواب دیاہے کہ یہ عرب کامحاورہ ہے اورقرآن میں بھی استعمال ہواہے کہ مقابل کی چیزوں کا جب ذکر کریں تو ایک جمع اور دوسرے کو مفرد لاتے ہیں.جیسے جَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّوْر کہ ظلمات جمع استعمال ہواہے اورنورمفرد.یہ فرق اس لئے کیا جاتا ہے کہ ایک لفظ کو مفرد بول کر افراد جماعت کی طرف اشار ہ کرتے ہیں اور دوسرے لفظ کو جمع استعمال کرکے جماعت کی طرف اشار ہ کرتے ہیں.بعض دوسرے علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یمین کالفظ جمع کے معنوں میں بھی بولاجاتاہے.(فتح البیان زیر آیت ھذا) اس آیت کایہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے عذاب کا ذکر کیاتھا اب اس کی دلیل بیان فرمائی ہے کہ ان کی سمجھ میں اتنا بھی نہیں آتاکہ اسباب کبھی پیداکرنے والے کے خلا ف ہوسکتے ہیں.کیایہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سورج کے سایہ میں تغیر ہوتارہتا ہے جس کی پیٹھ پر وہ ہوتاہے اس کاسایہ بڑھ جاتا ہے.پھر کیا خدا کو اتنی بھی طاقت نہیں جتنی تم سورج میں سمجھتے ہو.جب اللہ تعالیٰ محمد ؐرسول اللہ کی پیٹھ پرہوجائے گاکیااس کاسایہ نہ بڑھے گا اورترقی نہ ہوگی.اسی طرح جن کی پشت پر سے وہ ہٹ جائے گا کیا ان کے سائے سمٹ نہ جائیں گے ؟ یمین اور شمال کے الفاظ کی تفسیر میں مفسرین کو مشکل اس آیت میں جو یمین و شمال کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی تفسیر کرنے میں مفسروں نے بڑی مشکل محسوس کی ہے.وہ کہتے ہیں کہ سورج کے ادھر اُدھر ہونے سے سایہ کی لمبائی چھوٹائی تومشرق اورمغرب میں ہوتی ہے.مگر یہاں خدا تعالیٰ یمین وشمال بیان فرماتا ہے حالانکہ دائیں بائیں کاتعلق سایوں سے کچھ نہیں ہوتا.بعض نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یمین و شمال سے مراد مشرق و مغرب ہے کیونکہ اگر شمال کی طرف منہ کیا جائے تو مشرق و مغرب دائیں بائیں آجاتے ہیں (فتح البیان زیر آیت ھذا) مگریہ عام دنیا کے خلاف ہے.دنیا کاقانون یہ ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرکے سمتوں کی تعیین کر تے ہیں پس یہ توجیہ درست نہیں.یمین اور شمال کے الفاظ سے ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ اصل بات یہ ہے کہ اس مثال سے اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اورمکہ والوں کے اثرات کامقابلہ کرنااوریہ بتانا تھا کہ ان دونوں میں سے کس کے
Page 103
سائے بڑھیں گے اورکس کے گھٹیں گے.اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے والے تھے اوراس آیت میں بھی ہجرت کا ذکر ہوچکا ہے اس لئے آپؐ گویاشمالی علاقہ کی طرف جانے والے تھے اورمکہ والے آپ سے جنوب میں آنے والے تھے.پس اگر کوئی شخص دونوں ملکوں کی سرحد پر کھڑاہوکر مشرق کی طرف منہ کرے تومکہ اس کے دائیں آئے گااورمدینہ اس کے بائیں آئے گا.پس یمین وشمائل سے مکہ اورمدینہ مراد ہیں اور میرے نزدیک اسی وجہ سے یمین کو مفرد استعمال کیا ہے اورشمال کو جمع استعمال کیا ہے.جس سے اس طر ف اشارہ کیا ہے کہ تمہاراسایہ محدود ہوگا اوروہ بھی گھٹ جائے گااورمحمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) جوبائیں طرف کے ملک میں چلاجائے گا اس کے کئی سائے ہوں گے یعنی وہ مختلف جہات سے ترقی کرے گا.وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّ اورجو (شے بھی) آسمانوں میں ہے اور(نیز)زمین پر جو بھی جاندار (موجود )ہے اور(تمام )فرشتے بھی الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ۠۰۰۵۰ اللہ(تعالیٰ)کے حضورمیں ہی جھکے رہتے ہیں اوروہ بڑائی نہیں کرتے.حلّ لُغَات.دَآبَّۃدَبَّ(دَبًّا)کے معنے ہیں.مَشٰی عَلٰی ھِیْنَتِہِ کَمَشْیِ الطِّفْلِ وَالنَّمْلَۃ وَالضَّعِیْفِ.آہستہ آہستہ چلا جس طرح بچہ یا ضعیف یا چیونٹی چلتی ہے.اوردَابَّۃٌ دابٌّ کامؤنث ہے دَابَّۃٌ کے معنے ہیں مَادَبَّ مِنَ الْحَیَوانِ.ہروہ حیوان جو زمین پر ضرب لگاکر چلتا ہے.وغَلَبَ عَلٰی مَایُرْکَبُ وَیُحْمَلُ عَلَیْہِ الْاَحْمَالُ.دَابّۃ کااستعمال زیاد ہ تر اس حیوان کے لئے ہوتاہے جس پر سواری کی جاتی ہے یااس پر بوجھ لاداجاتا ہے.ویَقَعُ عَلَی الْمُذَکَّرِ وَاَلْھَاءُ فِیْھَا لِلْوَحْدَۃِ کَمَا فِی الْحَمَامَۃِ دَابّۃ کالفظ مذکر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اورۃ وحدت کی سمجھی جائے گی.یعنی دابّۃ کے معنے ہوں گے ایک حیوان(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے جوآسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے وہ بھی خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیںاورجو کوئی زمین میں بستے ہیں وہ بھی اس کے حکم کے ماتحت ہیں.پس جب خداکے قبضے میں سامان بھی ہیں اورسامانوں کے مدبّر ملائکہ بھی.توجب دونوں کو اس کی ترقی کے لئے لگادیاجائے گاتوکیوں نہ محمدؐرسول اللہ کاسایہ بڑھے گا.وَھُمْ لَایَسْتَکْبِرُوْنَ کا مطلب وَھُمْ لَایَسْتَکْبِرُوْنَ میں بتایاہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
Page 104
خدمت پرجن کو لگایاگیا ہے وہ توکامل فرمانبردار ہیں وہ توپورے زور سے کام میں لگ جائیں گے مگر تمہارے اتباع توتمہار ی اس طرح فرمانبرداری نہیں کریں گے اس لئے تمہارانظام کھوکھلااورناقص ہوجائے گا.لفظ دابة کے استعمال کی وسعت اس آیت میں دابّـة کالفظ استعمال کیا گیا ہے اوردابہ کاعام استعمال چوپایوں کے لئے ہے پھر اس جگہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ؟اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ دَبّ سے ہے جس کے معنے آہستگی سے چلنے کے ہیں اورا س کااسم فاعل دَابٌّ اورمؤنث دَابَّۃٌ ہے انہی معنوں میں اس جگہ یہ لفظ استعمال ہواہے اورانسان اس میں شامل ہیں.يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا وہ اپنے رب سے جو ان پر غالب ہے ڈرتے رہتے ہیں.اورجس بات کا انہیں حکم دیاجاتاہے يُؤْمَرُوْنَؑ۰۰۵۱ (وہی)کرتے ہیں.تفسیر.يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَکے الفاظ میں ہاروت و ماروت کے قصے کا ابطال یہ ملائکہ کی صفت بیان فرمائی ہے اس سے ہاروت ماروت کا قصہ بھی باطل ہو جاتا ہے.فرشتے تواللہ تعالیٰ سے خوف کرتے اور اُس کے حکمو ں پر عمل کرتے ہیں وہ اس کے حکمو ںکوتوڑنے والے نہیں ہوسکتے.مِنْ فَوْقِهِمْ.یہ ترکیب میں رب کاحال ہے یعنی فرشتے اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جبکہ وہ ان کے اوپر ہے یعنی ان پر غالب ہے.وَ قَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْۤا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ١ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ اوراللہ(تعالیٰ)نے(ہمیشہ ہرقوم کو یہی )فرمایا ہے (کہ)تم دومعبود مت بنائو.وہ (یعنی معبود برحق تو)ایک ہی ہے وَّاحِدٌ١ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ۰۰۵۲ پس تم مجھ سے ہی (ڈرو)پھر(تم سے کہتا ہوں کہ)مجھ سے ہی ڈرو.حلّ لُغَات.اِلٰھَیْن اِلٰھَیْنِ اِلٰہٌ سے تثنیہ کاصیغہ ہے اوراَلْاِلٰہُ کے معنے ہیں اَلْمَعْبُوْدُ مُطْلَقًابِحَقٍّ اَوْ
Page 105
بِبَاطِلٍ لِاَنَّ الْاَسْمَائَ تَتَّبِعُ الْاعْتِقَادَ لَا مَاعَلَیْہِ الشَّیْءُ فِیْ نَفْسِہِ.یعنی ہر معبود پر اِلٰہٌ کا لفظ بولتے ہیں خواہ وہ سچا ہویاجھوٹا.کیونکہ اشیاء کانام اعتقاد پررکھاجاتاہے نہ اس بات کو مدنظررکھ کرکہ وہ چیز اپنے نام کے مطابق اپنے اندرحقیقت بھی رکھتی ہے یانہیں.(اقرب) وَاحِدٌ کے معنے کے لئے دیکھو رعدآیت نمبر۱۷.اَلْوَاحِدُ بِمَعْنَی الْاَحْدِ اَیْ اَلْمُنْفَرِدِ الَّذِیْ لَانَظِیْرَ لَہٗ اَوْلَیْسَ مَعَہٗ غَیْرُہٗ.ایسایکتا کہ جس کا کوئی نظیر نہ ہو یا اس کا کوئی شریک نہ ہو.اور انہی معنوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوا ہے.(اقرب) فَارْھَبُوْن اِرْھَبُوا.رَھَبَ سے جمع مخاطب کا صیغہ امر ہے.اوررَھِبَ الرَّجُلُ رَھْبَۃً کے معنے ہیں : خَافَ.ڈر گیا (اقرب) اِرْھَبُوْنِ اصل میںاِرْھَبُوْنِیْ تھا.نِیْ کو گرایاگیا.پھر نِ کو جسے نون وقایہ کہتے ہیں لایا گیا اورصرف کسرہ پر اکتفاء کیا گیا.پس اِرْھَبُونِ کے معنے ہوں گے کہ مجھ ہی سے ڈرو.(اس کے لئے دیکھو سورۃ بقرہ ع ۵) اِرْھَبُوْا.جمع مخاطب کا صیغہ امر ہے اور رَھُبَ الرَّجُلُ (یَرْھَبُ رَھْبَۃً) کے معنے ہیں خَافَ ڈر گیا (اقرب) اِرْھَبُوْنِ اصل میں اِرْھَبُوْنِیْ تھا.ی کو گراد یا گیا اور نونِ وَقایۃ کے کسرہ پر اکتفا کیا گیا.اِرْھَبُوْنِ کے معنے ہیں مجھ سے ڈرو.تفسیر.اِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ کی ترکیب فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ.اصل میں فَاِیَّایَ ارْھَبُوْا فَارْھَبُوْنِ ہے جس کے معنے ہیں پس مجھ ہی سے ڈروہاں میں پھر کہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو اِرْھَبُوْا کو حذف کردیاگیا اورفَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِرہ گیا.فَاِيَّايَ بعد کے فعل یعنی فَارْهَبُوْنِ کامعمول نہیں بن سکتا.کیونکہ درمیا ن میں ف آئی ہے.اس لئے اس فعل سے پہلے ایک اِرْھَبُوْا محذوف ماناجائے گا.اس طرزِکلام سے مقصود مضمون پرزوردینا ہوتاہے.یعنی رہب اورخوف صرف خداہی سے ہوناچاہیے.اِلٰھَیْنِ اثْنَیْنِ کے الفاظ میں جمع کو چھوڑ کر تثنیہ کے ذکر کرنے میں تین حکمتیں اِلٰھَیْنِ اثْنَیْنِ.یہ جو فرمایاکہ دومعبود نہ بنائو اس پر اعتراض ہوتاہے کہ دوکالفظ کیوں فرمایا.جمع کاصیغہ رکھ کر یہ کیوں نہ فرمایا کہ لَاتَتَّخِذُوْآاٰلِھَۃً ایک سے زیادہ معبود نہ بنائو.اس سے تویہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسے زائد خدابنانے جائز ہیں.ایسا اعتراض قلّتِ تدبر سے پیدا ہوتاہے کیونکہ اس کے آگے ہی یہ الفاظ ہیں اِنَّمَاھُوَ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ خداصرف ایک ہے.ان الفاظ کی موجودگی میں یہ شبہ پیداہی نہیں ہوسکتا کہ دوسے زیادہ خداماننے جائز ہیں.پس دوکا لفظ ایک کے مقابل
Page 106
پر زوردینے کے لئے رکھا گیا ہے اورمراد یہ ہے کہ خداصر ف ایک ہے.پس زیادہ خدابنانے توالگ رہے تم کودوخدابھی نہیں بنانے چاہئیں.دوسری حکمت ان الفاظ کے اختیار کرنے میںیہ ہے کہ مشرک بھی اللہ اور دوسرے معبودوں میں فرق کرتے تھے وہ سب دنیا کے پیداکرنے والے کوتو اللہ کہتے تھے اور دوسرے معبودانِ باطلہ کومحدوداختیارات والے خداسمجھتے تھے.یاتو اس لحاظ سے کہ انہیں محدود طاقتیں حاصل تھیں مثلاً کوئی مینہ برساتاتھا ،کوئی اولاد دیتا تھا ،کوئی بیماریوں سے شفادیتاتھا وغیرہ وغیرہ.اوریااس لحاظ سے کہ کوئی خداایک قبیلہ کی حفاظت کرتا تھا توکوئی دوسرے کی.چنانچہ ان کے ہاں جس طرح مختلف اغراض کے لئے الگ الگ دیوتاتھے اسی طرح مختلف اقوام کے لئے بھی الگ الگ دیوتا تھے.گویاایک خداتوقادرمطلق تھا اور دوسرے معبود محدود اغراض اورمحدود علاقوں کے لئے تھے.اس طرح خدائوں کی دو قسمیں ہوجاتی ہیں.ایک قسم قادرمطلق خدا کی جو ان کے نزدیک بھی صرف ایک تھا اوردوسری قسم محدود اختیارات اورمحدود علاقوں کے خدائوں کی جواُن کے نزدیک بہت سے تھے (تفسیر کبیر لامام رازی سورۃ الزمر زیر آیت ولئن سألتھم من خلق السموت).پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ جوفرمایا ہے کہ دوخدانہ بنائو اس سے مراد یہ ہے کہ دو قسم کے خدانہ بنائو.خداایک ہی ہے اس کے سواکوئی اورقسم کا خدانہیں ہے.تیسری حکمت ان الفاظ کے استعمال کرنے میں یہ ہے کہ اس میں مجوس کے ا س عقیدہ کابطلان کیا گیا ہے جو دوخدامانتے ہیں ایک خیر کا خدادوسراشرکا خدا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے دوخداموجود نہیں ہیں خداصرف ایک ہی ہے جزائے خیر بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اورجزائے شربھی اُسی کی طرف سے آتی ہے پس دوخدانہ بنائو.اس آیت میں بتایاہے کہ جب ایک ہی خداہے توپھر بتائوکہ شریعت اس کے سوااورکون بناسکتا ہے شریعت کابنانااسی کے اختیار میں ہوگا.اس آیت میں ہجرت اور اس کے نتائج کی پیشگوئی کی طرف اشارہ اس آیت میں ہجرت اوراس کے نتائج کے متعلق جوپیشگوئی کی گئی تھی اس کی طرف بھی اشارہ کیاگیا ہے اوربتایاگیا ہے کہ ان واقعات کے پوراہونے پر تم کومعلوم ہوجائے گاکہ خداایک ہی ہے اس کے سواکوئی دوسراخدانہیں یعنی مسلمانوں کی ترقی اورکامیابی اللہ تعالیٰ کی توحید اورذات کا ایک زبردست ثبوت ہوگی.ان آیات میں قرآ ن کریم کی تعلیم اورکفارکی تعلیم کا مقابلہ بھی ہورہاہے اوربتایاجارہاہے کہ کیا کبھی انسان قرآن کریم کی تعلیم سے مستغنی ہو سکتا ہے تم لوگوں نے اپنی عقل سے کام لے کر بے شمار معبود بنارکھے ہیں یہ الہام ہی
Page 107
ہے جوسچی توحید کی طر ف رہنمائی کرتاہے اورانسانی دماغ کوتشطّط اورپراگندگی سے بچاتاہے.وَ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا١ؕ اورجوکچھ (بھی)آسمانوں اورزمین میں (پایاجاتا)ہے اِسی کا ہے اوراطاعت ہمیشہ اسی کاحق ہے پھر کیا تم اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ۰۰۵۳ اللہ(تعالیٰ)کے سوااوروں کواپنے بچائوکاذریعہ بناتے ہو.حل لغات.الدّیْنُ الدِّیْنُکے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۷۷.دَانَ دِیْنًا: اَطَاعَ.دَانَ جس کا مصدر دَیْنٌ ہے اس کے معنے ہیں اطاعت کی فُلَانًا: خَدَمَہُ خدمت کی.خدمت ادا کی.حَکَمَ عَلَیْہِ.حکم لگایا فیصلہ کیا.اَلدِّیْنُ: اَلطَّاعَۃُ دین کے معنی ہیں فرمانبرداری.القَضَاءُ.فیصلہ.(اقرب) وَاسْتُعِیْرَ لِلشَّرِیْعَۃِ.اور یہ لفظ بالواسطہ شریعت یا قانون کے معنے میں بھی استعمال ہوتا ہے.(مفردات) واصبًا وَصَبَ الشَّیْءُ(یُصِبُ وَصُوْبًا) کے معنے ہیں دَامَ وَثَبَتَ.کوئی چیز قائم و دائم رہی.وَصبَ الدَّیْنُ:وَجَبَ.قرضہ کی ادائیگی واجب ہوگئی.وَصَبَ فُلَانٌ عَلَی الْاَمْرِ : وَاظَبَ وَاَحْسَنَ الْقِیَامَ عَلَیْہِ کسی امر پر دوام اختیار کیا اوراس پراچھی طرح کاربند رہا.اَلْوَاصِبُ : الدَّائِمُ.ہمیشہ رہنے والا.لَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا کے معنے ہیں دائـمًاکہ اطاعت ہمیشہ اسی کاحق ہے (اقرب) تفسیر.آیت وَ لَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا میں شرک کے رد میں ایک زبردست دلیل شرک کے ردّمیں یہ ایک نہایت زبردست دلیل ہے جسے قرآن مجید نے متعدد جگہ پر پیش کیاہے.فرماتا ہے آسمان و زمین کے نظام پر غور کر و.کائنا ت عالم کو دوربین نگاہ سے دیکھو توتمہیں سب جگہ پر ایک ہی قانون جاری نظر آئے گااوریہ تمام اشیاء ایک انتظام میں منسلک نظرآئیں گی جب قانون ایک ہے توبادشاہ دویازیادہ کیسے ہوسکتے ہیں.اگر کوئی دوسرا خداہوتا توضروری تھا کہ ہمیں دنیا میں قانون کااختلاف نظرآتا.کیونکہ دوسرے خدا کاوجود ماننے کی صورت میں نظامِ عالم کی دوہی صورتیں ہوسکتی ہیں:.
Page 108
۱.یہ کہ وہ پہلے خدا کی اطاعت کرے اوراس کے احکام کے ماتحت چلے.اس صورت میں اس کاہونا نہ ہونابرابر ہے.کیونکہ جوکام ایک کرسکتاہے دوکو اس کام پر لگانے کی کیاضرورت ؟ ۲.وہ پہلے خداکے علاوہ کوئی اورنیاکام کرتاہو اوراس کاقانون اورنظام الگ ہو.اس صورت میں ضروری ہے کہ نظام عالم میں اختلاف نظر آوے.لیکن چونکہ واقعہ میں ایسا نہیں ہے لہٰذامانناپڑے گا کہ دوسراخداہی کو ئی نہیں.صرف ایک ہی واحد ویگانہ خداہے.لَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا.اس میں بتایا ہے کہ دوسری صورت ایک سے زیادہ خدائوں کی یہ ہوسکتی تھی کہ ایک خداایک زمانہ تک کام کرتا اوراس کے بعد وہ معطل ہوجاتااوراس کی جگہ دوسراخدالے لیتا.لیکن یہ بات بھی واقعا ت سے غلط ثابت ہورہی ہے.جوقانون قدرت شروع سے چلایا گیا ہے وہی آج تک چلا آرہاہے.لاکھو ں بلکہ کروڑو ں سال گذرے مگر اس کے قانون میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی.اس کاقانون اٹل ہے پس ایسے خدا کی موجودگی میں کہ جو زمین و آسمان کامالک ہو اورجس کاقانون ازل سے ابد تک ہو دوسرے خدا کاوجو د ماننا سخت غلطی اور بے وقوفی ہے.وَ مَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ اورجونعمت بھی تمہارے شامل حال ہے وہ اللہ (تعالیٰ)ہی کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں (کوئی تنگی اور)تکلیف فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَۚ۰۰۵۴ پہنچتی ہے تو(اس وقت بھی)تم اسی کے حضورفریاد کرتے ہو.حلّ لُغَات.نِعْمَۃٍ اَلنِّعْمَۃُ کے معنے ہیں :اَلصَّنِیْعَۃُ وَالْمِنَّۃُ.احسان.مَااَنْعَمَ بِہِ عَلَیْکَ مِنْ رِزْقٍ وَمَالٍ وَغَیْرِہٖ.وہ مال یا رزق یا اس کے علاوہ کوئی اورچیز جو بطورانعا م ملے.اَلْمَسَرَّۃُ.خوشی.اَلْیَدُ الْبَیْضَاءُ الصَّالِحَۃُ.ایسااحسان جس میں کوئی کدورت اورکمی نہ ہو.وَفِیْ الْکُلّیَاتِ.’’اَلنِّعْمَۃُ فی اَصْلِ وَضْعِھَا اَلْحَالَۃُ الَّتِیْ یَسْتَلَذُّ ھَا الْاِنْسَانُ وَ ھٰذَامَبْنِیٌّ عَلٰی مَااشْتُھِرَ عِنْدَھُمْ مِنْ اَنَّ الفِعْلَۃَ بِالْکَسْرِ لِلْحَالَۃِ وَبِالْفَتْحِ لِلْمَرَّۃِ.‘‘اورکلیات میں یوں لکھا ہے کہ نعمت اصل وضع کے لحاظ سے اس حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان لذت اٹھاتاہے اوریہ اس بناء پر ہے کہ حالت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں فِعْلَۃٌ اور کسی کام کے ایک دفعہ
Page 109
ہونے کے لئے فَعْلَۃٌ کاوزن لاتے ہیں اورنِعْمَۃٌ فِعْلَۃٌ کے وزن پر ہے اس لئے اس میں نعمت والی حالت کے معنے پائے جاتے ہیں.نِعْمَۃُ اللہِ:مَااَعْطَاہُ اللہُ لِلْعَبْدِ مِمَّا لَا یَتَمَنّٰی غَیْرَہُ اَنْ یُعْطِیَہٗ اِیَّاہُ.اللہ کی نعمت و ہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتاہے اورپھر بندہ اللہ کے سواکسی اورسے یہ خواہش نہیں رکھتا کہ وہ اسے دے.اس کی جمع اَنْعُمٌ اورنِعَمٌ آتی ہے اورجب فُلَانٌ وَاسِعُ النِّعْمَۃِ کہیں تواس کے معنے ہوں گے وَاسِعُ الْمَالِ یعنی فلاں مالدارہے.(اقرب) اَلضُّرّ اَلضُّرّ کے معنے کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۸۹.اَلضُّرُّ ضِدُّ النَّفْعِ.ضُرّ کے معنے ہیں نقصان.سُوْءُ الْحَالِ وَالشِّدَّۃِ.تنگ حالی وَفِی الْکُلّیَاتِ اَلضَّرُّ بِالْفَتْحِ شَائِعٌ فِی کُلِّ ضَرَرٍ وبِالضَّمِّ خَاصٌ بِمَا فِی النَّفْسِ کَمَرَضٍ وَھُزَالٍ کلیات میں یوں لکھا ہے کہ ضَرٌّ کے معنے خاص اس تکلیف کے ہیں جو خود نفس میں ہو جیسے بیماری یا لاغر پن وغیرہ لیکن ضُرٌّ کا لفظ عام ہے اور ہر تکلیف پر بولا جاتا ہے.(اقرب) تَجْأَرُوْنَ تَجْأرُوْنَ جَأرَ سے مضارع جمع مخاطب کاصیغہ ہے.اورجَأَرَالدَّاعِیَ جَأْرًا کے معنے ہیں رَفَعَ صَوْتَہٗ بِالدُّعَاءِ پکارنے والے نے اونچی آواز سے پکارا.جَأَرَاِلَی اللہِ بِالدُّعَاءِ:ضَجَّ وَتَضَرَّعَ وَاسْتَغَاثَ اللہ کے حضور عاجزی سے فریاد اوردعاکی اور اُسی سے مد دچاہی.وَمِنْہُثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ اورآیت اِذَامَسَّکُمْ … الخ میں تَجْأَرُوْنَ کے معنی عاجز ی کرنے اورفریاد کرنے کے ہیں(اقرب) تفسیر.توحید کی تائید میں ان دلائل کا ذکر جو کفار کی جانوں میں موجود تھے اس آیت میں ان آیات اورنشانات کا ذکر فرمایا ہے جوتوحید کی تائید میں خود ان کی جانوں میں موجودتھے.فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تم کو سب نعمتیں ملی ہیں.کیونکہ جس قدرنعمتیں ہیں وہ ایک ہی نظام کاحصہ ہیں.مگر باوجوداس کے تم بعض نعمتوںکو دوسرے معبودوں کی طرف منسوب کردیتے ہو.لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جب کبھی کوئی سخت قوی آفت آتی ہے تم کو اپنے معبودان باطلہ بھول جاتے ہیں اوراسی ایک خدا کی طرف جو حقیقی خداہے جھک جاتے ہو.یہ اس امر کاثبوت ہے کہ تمہارے دل شرک پر مطمئن نہیں.پس جب شرک پر تم خود مطمئن نہیں تواس پر اس قدر زورکیوں دیتے ہو.مشرکین کا تکلیف کے وقت معبودان باطلہ سے اعراض یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ شدید مصائب کے وقت میں لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جھکتے ہیں.مسیحی جو مسیح کو خدائی کا مقام دیتے ہیں اس جنگ میں جو
Page 110
اس وقت جرمنی اورانگلستان کے ساتھ ہورہی ہے مسیح کو نہیں پکار رہے بلکہ ایک خدا کوپکاررہے ہیں.اگرانہیں مسیح کی خدائی پر پورایقین ہوتا توکبھی ایسانہ کرتے.بدر کی جنگ کے موقع پر جب کہ گھمسان کا رَن پڑاتھا توکفارنے لات اورعزیٰ کو نہیں پکارا.ابوجہل نے بھی ان باطل معبودوں سے دعانہیں کی.بلکہ کہا تویہی کہا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (الانفال :۳۳) کہ اے اللہ اگر یہ مذہب اسلام سچا ہے اورہم اس کی مخالفت ضد کی وجہ سے کررہے ہیں توہم پرآسمان سے پتھر برسایااس کے سواکوئی اوردردناک عذاب ہمیں دے.اور خدائے واحد نے اس کی دعاسن بھی لی اوربدر میں ان پر پتھروں کی بارش بھی نازل کی اوراَورکئی قسم کے دردناک عذاب بھی ان پر نازل کئے.(بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال باب قولہ و اذ قالوا اللّھم..)اگران لوگوں کے دلوں میں لات اورعزیٰ کاہی گہرانقش واثرہوتاتوانہی کو اس مصیبت میں پکارتے.مگر ایسانہیں ہوابلکہ انہوں نے خدا تعالیٰ ہی کوبلایا اوریہی فطرت کی شہادت ہے.ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کردیتاہے توتم میں سے بعض لوگ جھٹ(اوروںکو)اپنے رب کاشریک يُشْرِكُوْنَۙ۰۰۵۵ ٹھہرانے لگتے ہیں.تفسیر.آیت میںبِرَبِّهِمْ کے الفاظ استعمال کرنے کی حکمت بِرَبِّهِمْ.کالفظ استعمال فرما کر انہیں شرم اورغیرت دلائی ہے کہ تم اپنے ہی رب کے شریک ٹھہراتے ہو.حالانکہ انسان کو اپنی چیز کی ایک غیرت ہوتی ہے وہ توتمہارااپنارب ہے تمہیں اس کے ساتھ کوئی ضدتو نہیں کہ ضروراس کے ساتھ شریک ٹھہرائو.پھرکیا وجہ ہے کہ مصیبت کے وقت توا س کو یاد کرتے ہو اورجب مصیبت ٹل جاتی ہے توپھر تم کو اپنے جھوٹے معبود یاد آجاتے ہیں.
Page 111
لِيَكْفُرُوْا بِمَاۤ اٰتَيْنٰهُمْ١ؕ فَتَمَتَّعُوْا١۫ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جوکچھ ہم نے انہیں دیاہے وہ اس کاانکار کردیتے ہیں اچھا؎ تم عارضی (اوروقتی سامانوں سے ) فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ۰۰۵۶ نفع اٹھالواور(اس کا انجام بھی )تم جلد معلوم کرلو گے.حل لغات.؎ فاء کاترجمہ اس جگہ ’اچھا ‘زیادہ درست معلوم ہوتاہے.تفسیر.لِیَکْفُرُوْا میں لام.لام عاقبت ہے لِیَکْفُرُوْا میں لام.لام عاقبت ہے اورمراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب تم پر سے مصیبت ٹلادیتاہے تواس کانتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے اس کاشکریہ اداکرنے کے تم اس کے فضل کاانکار کردیتے ہو اورکہتے ہو کہ یہ فضل فلاں دیوتا کی وجہ سے نازل ہواہے.جب تمہاری یہ حالت ہے تو تم دائمی فضل کے مستحق نہیں ہوسکتے.ہم تمہاری ہدایت کی غرض سے اوراپنے رحم سے کام لیتے ہوئے چند بارتوتمہاری دعائوں کو سن کر مصائب ٹال دیں گے مگر ہمیشہ توایسانہ ہوگا آخر ایک دن ہم تمہاری دعائوں کو ردّ کردیں گے اورعذاب میں مبتلاکردیں گے.وَ يَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ١ؕ تَاللّٰهِ اورجو کچھ ہم نے انہیں دیاہے اس میں سے ایک حصہ و ہ (اپنے )ان (جھوٹے معبودوں)کے لئے مخصوص کردیتے لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ۰۰۵۷ ہیں جن (کی حقیقت )کے متعلق وہ (کچھ )علم نہیں رکھتے.اللہ(تعالیٰ)کی قسم جوکچھ تم (جھوٹ سے کام لے کر )اپنے پاس سے گھڑتے رہے ہو (ایک دن ) اس کی نسبت تم سے یقیناً باز پرس ہوگی.حلّ لُغَات.النَّصِیْبُ.اَلنَّصِیْبُ الحَظُّ:حصہ (اقرب) تفسیر.اس آیت میں شرک کی ایک اور شناعت شرک کی ایک اورشناعت اس آیت میں بیان کی گئی ہے اوروہ یہ کہ الٰہی نعمتوںکو ایسے وجودوں کی طرف منسوب کیاجاتا ہے جن کے وجود کاخود کوئی ثبوت
Page 112
نہیں.یہ دلیل شرک کے ردّ میں ایک زبردست ثبوت ہے.مشرکوں نے شرک کی تائید میں بعض ایسے فلسفیا نہ مسائل بنارکھے ہیں کہ ان میں پڑ کر کمزوردماغ کے آدمی کچھ حیران سے ہوجاتے ہیں اورشرک اورتوحید میں فرق کرنا ان کے لئے مشکل ہوجاتا ہے.اس آیت میں شرک کے متعلق ایک ایسی عام فہم دلیل دی گئی ہے جو ان سب فلسفیانہ وسوسوں کورد کردیتی ہے.اوروہ یہ کہ اس اصولی بحث کوجانے دو کہ ایک سے زیاد ہ معبود ہوسکتے ہیں یا نہیں.کسی چیز کاہوسکنا اَورامر ہے اورہونا اَورامر ہے.فرض کرلو کہ ایک سے زیادہ معبود ممکن ہوں مگر اس سے یہ توثابت نہیں ہوجاتا کہ کوئی خاص بت یاخاص انسان جسے خدا تعالیٰ کا شریک بنایاجاتاہے وہ بھی سچا معبود ہے.اس امر کاثبوت کہ کوئی شخص یابت معبود سچا ہے توالگ دیناہوگا.فرماتا ہے اپنے ایک ایک معبود کولے لو کیاان میںسے کسی کی خدائی کاثبوت بھی تمہارے پاس ہے.اگر کسی معبود کی خدائی کاثبوت بھی تمہارے پاس نہیں توصر ف فلسفیانہ دلائل شرک کی تائید میں دے کر تم توحید کے حملہ سے کس طر ح بچ سکتے ہو.یہ وہ دلیل ہے جس کے سامنے کوئی مشرک نہیں ٹھہر سکتا.ہم فرض کرلیتے ہیں کہ ایک سے زیادہ خداممکن ہیں.مگریہ کیونکر ثابت ہواکہ کالی بھی خداہے یارام یاکرشن بھی خداہیں یا مسیح اورایسے ہی ان لوگوں کے مزعومہ خدا،خداہیں.ان کے خداہونے کاتو الگ ثبوت دینا پڑے گا جوکبھی کوئی مشرک نہیں دے سکتا.وہ ہمیشہ عام فلسفیانہ دلائل شرک کی تائید میں پیش کرے گا.اپنے مزعومہ معبود کی تائید میں کبھی کوئی معقول دلیل نہ دے گااورنہ دے سکے گا.کیونکہ شرک کی تائید میں فلسفیانہ دلائل دینا اوربات ہے اورایک کمزور وجود کو خداثابت کر نا اوربات ہے.اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ نے ان سب وجودوں کے متعلق جن کو خدا مانا جاتا ہے ایسے زبردست شواہد ان کے کمزوراوربے بس ہونے کے پیداکررکھے ہیںکہ جب اس طرف رخ کیاجائے مشرک کی سب شیخی کرکری ہوجاتی ہے.لِمَالَایَعْلَمُوْنَ کے دو معنی لِمَالَایَعْلَمُوْنَ سے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ ان معبودوں کویہ حصہ دیتے ہیں جومعبود اس بات تک کو نہیں جانتے کہ انہیں خدا تعالیٰ کی صفات د ی جارہی ہیں.مثلاً بُت.نہریں.دریا.پہاڑوغیرہ جن کو لوگ خدابناتے ہیں خود بے جان اشیاء ہیں.ایسا ہی حضرت عیسیٰؑ اور حضرت امام حسینؓ ہیں.لوگ ان کی طرف الوہیت کو منسوب کرتے ہیں اورکہتے ہیںکہ انہوں نے فلاں فلاں چیز دی مگر اُن بے چاروں کو اس بات کاپتہ بھی نہیں(انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۱.تحفہ اثنا عشریہ از علامہ الہند حضرت مولانا شاہ عبد العزیز اردو ترجمہ مولانا عبد المجید باب دوم در مکائد شیعہ کید نمبر ۶۶).کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی دعویٰ خدائی کانہیں کیا.اس صورت میں لَایَعْلَمُوْنَ کی ضمیر معبودوں کی طرف مانی جائے گی.
Page 113
دوسرے معنے وہی ہیں جواوپر بیان ہوچکے ہیں یعنی ان ہستیوں کی طرف خدا تعالیٰ کے افعال کو منسوب کرتے ہیں جن کے خداہونے کی ان کے پا س کوئی دلیل نہیں.ان معنوں کے روسے لَایَعْلَمُوْنَ کی ضمیر یَجْعَلُوْنَ کے فاعل کی طرف پھر ے گی.تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ کا مطلب تَاللّٰهِ لَتُسْـَٔلُنَّ پوچھنے سے مراد خالی دریافت کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ سزادیناہوتا ہے اوریہ ہر زبان و ملک کامحاورہ ہے.مطلب یہ کہ تمہارے اس افتراء کی تم کو ضرور سزاملے گی.بعض لوگوں کا تَاللّٰهِ کے لفظ سے غلط استدلال بعض نادان تَاللّٰهِ کے لفظ سے یہ استدلال کیا کرتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ کلام خدا کانہیں ورنہ یہ کیوں کہاجاتاکہ خدا کی قسم.بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں اپنی قسم ہے(تفسیر القرآن از پادری ویری جلد ۳ ص ۳۵ ).لیکن یہ استدلال درست نہیں کیونکہ شاہانہ کلام میں اس قسم کا طرز بیان جائز ہوتاہے.کیونکہ نام کے اظہار سے رُعب پیداکرنا مقصود ہے.با پ اپنے بیٹے پر اثر ڈالنے کے لئے بعض دفعہ یہ کہتاہے کہ تمہاراباپ تم کو یہ حکم دیتا ہے.اس کے یہ معنے نہیں ہوتے کہ بولنے والا باپ نہیں بلکہ کوئی اور ہے.اسی طرح بادشاہ خاص زوردینے کے لئے کہاکرتے ہیں کہ تمہارابادشاہ تم کو یوں حکم دیتا ہے اوراس سے یہ مراد نہیں لی جاسکتی کہ بادشاہ اس وقت اپنی بادشاہت کا انکار کر کے کسی اَورکی بادشاہی کااعلان کررہا ہے.وَ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ١ۙ اوروہ اللہ (تعالیٰ)کی طرف لڑکیاں منسوب کرتے ہیں (یہ کیساجھوٹ ہے)وہ پاک(ذات)ہے اور وَ لَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ۰۰۵۸ (لطف یہ کہ)انہیں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے )وہ کچھ حاصل ہے جو وہ چاہتے ہیں.حلّ لُغَات.سُبْحَانَہٗ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۱۹.سُبْحَانَ اللہِ اَیْ اُبْرِّیُٔ اللہَ مِنَ السُّوْءِ بَرَاءَ ۃً.سبحان کے معنی عیوب سے پاک سمجھنے اور پاک کرنے کے ہیں.(اقرب) یَشْتَھُوْنَ :یَشْتَھُوْنَ اِشْتَہٰی سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اوراِشْتَہٰی کے معنے ہیں.کسی چیز کو پسند کیا.اوراس کے لینے کی تمنا کی (اقرب) پس وَلَہُمْ مَّایَشْتَھُوْنَ کے معنے ہوں گے.ان کو وہ کچھ حاصل ہے
Page 114
جو وہ چاہتے ہیں.تفسیر.اس آیت کایہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اس لئے ناراضگی ہے کہ وہ اس کی طر ف بیٹے کیوںمنسوب نہیں کرتے اوربیٹیاں کیوں منسوب کرتے ہیں.وہ توبیٹوں کے عقیدہ پر بھی ویسا ہی ناراض ہوتاہے جیسے بیٹیوں کے عقیدہ پر.چنانچہ دوسری جگہ فرمایا ہے تَکَادُالسَّمٰوٰتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْہُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ ھَدّاً اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا(مریم :۹۲) قریب ہے کہ آسمان پھٹ کرگرجائیں اورزمین شق ہوجائے اورپہاڑ گرجائیں کیونکہ یہ لوگ رحمٰن خدا کاایک بیٹاتجویز کرتے ہیں.پس بیٹوں کا ذکر کرکے مشرکوں کی کم عقلی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اوریہ بتایا ہے کہ غلط راہ پر چل کر انسان ایسی باتوں میں مبتلا ہوجاتا ہے جو خود اس کےاپنے مسلّمات کے رو سے قابل اعتراض ہوتی ہیں.چنانچہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں.اگرعقل سے کام لیتے توجس چیز کو یہ اپنے لئے ذلت کاموجب سمجھتے ہیں اس چیزکو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرتے.یہ اس امر کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ الہام کے بغیر ہدایت کاراستہ تلاش کرنے میںانسان کیسی کیسی موٹی غلطیاں کرجاتا ہے.پھر باریک مسائل میں وہ کیوں غلطی نہ کرے گا.پس سچا راستہ بتاناصر ف اللہ تعالیٰ ہی کاکام ہے.اس کے جواب میں ممکن تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم تو خدا کی طرف کوئی برائی منسوب نہیں کرتے.لڑکیا ںبھی خدا کی ہی ایک نعمت ہیں اُسی کی پروردہ ہیں.اس لئے یہ کوئی عیب نہیں.اس کاجوا ب اگلی آیت میں دیاگیاہے.وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ اورجب ان میں سے کسی کو لڑکی (کی پیدائش )کی بشارت دی جائے تو اس کا منہ جب کہ وہ اپنے غیظ (وغضب) كَظِيْمٌۚ۰۰۵۹ کو (سینہ میں )دبارہاہوتا ہے سیاہ ہوجاتا ہے.حلّ لُغَات.بُشِّرَبُشِّرَ بَشَّرَ سے مجہول کاصیغہ ہے.اوربشَّرَہٗ کے معنے ہیں اَخْبَرَہٗ فَفَرِحَ اس کوایسی خبر دی جس سے وہ خوش ہوا(اقرب) کَظِیْمٌ کَظِیْمٌ کے معنے ہیں اَلْمَکْرُوْبُ.رنجیدہ (اقرب)مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر۸۵.
Page 115
الْکُظُوْمُ اِحْتِبَاسُ النَّفْسِ.کُظُوْمٌ کے معنے ہیں سانس کا رکنا.وَیُعَبَّرُ بِہِ عَنِ السُّکُوْتِ.خاموشی کے موقعہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے.کَظَمَ الْغَیْظَ.حَبَسَہٗ.غَیْظ کے ساتھ جب کَظَمَ کا لفظ آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں غصہ کو روک لیا.کَظَمَ السِّقَاءَ شَدَّہٗ بَعْدَ مِلْئِہِ مَانِعًا لِنَفَسِہِ.اور جب سقاء کے لئے کَظَمَ کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں مشکیزہ بھر کر پانی کو محفوظ رکھنے کے لئے اس کا منہ بند کر دیا.پس کظیم ایسے شخص کو کہیں گے کہ جو اپنے اندر غصہ کو دبائے رکھے اور ظاہر نہ ہونے دے.(مفردات) تفسیر.یعنی ان کی یہ حالت ہے کہ ان میںسے کسی کوجب بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تواس کامنہ کالا ہو جاتا ہے اورغم اورشرم کے جذبات کو بمشکل دبارہاہوتاہے.لیکن یہ شخص جوبیٹی کی پیدائش پر سیاہ روہو جاتا ہے اس ہستی کی طر ف جونورہی نور ہے اسی چیز کو جسے اس قدر قابل شرم سمجھتا ہے منسوب کردیتاہے.يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ١ؕ اَيُمْسِكُهٗ (اور) جس بات کی اسے بشارت دی گئی ہے اس کی (مزعومہ)شناعت کے باعث وہ لوگوں سے چھپتا(پھرتا)ہے عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ١ؕ اَلَا سَآءَ مَا (اورسوچتاہے کہ )آیاوہ اسے (آئندہ آنے والی)ذلّت کے باوجود(زندہ)رہنے دے یا اُسے (کہیں)مٹی میں يَحْكُمُوْنَ۰۰۶۰ گاڑ دے.سنو!جورائے وہ قائم کرتے ہیں بہت بری ہے.حلّ لُغَات.یَتَوَارٰی :یَتَوَارٰی تَوَارَی سے مضارع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اورتَوَارٰی کے معنے ہیں.اِسْتَتَرَ چھپ گیا(اقرب)پس یتواریٰ کے معنےہوں گے وہ چھپتا ہے.ھُوْنٌ ھَانَ الرَّجُلُ ھُوْنًـا کے معنے ہیں.ذَلَّ وَحَقَرَوہ ذلیل اورحقیر ہوگیا.ضَعُفَ.کمزورہوگیا.اَلْھُوْنُ ھَانَ کامصدرہے.نیز اس کے معنے ہیں اَلْخِزْیُ.رسوائی(اقرب) یَدُسُّہٗ یَدُسُّہٗ دَسَّ سے مضارع واحد مذکر غائب کاصیغہ ہے.اوردَسَّ الشَّیْءَ تَحْتَ التُّرَابِ کے معنی ہیں:اَدْخَلَہٗ فِیْہِ.وَدَفَنَہٗ تَحْتَہٗ واَخْفَاہٗ کسی چیز کو زمین میں دباکر مخفی کردیا (اقرب)پس اَمْ یَدُسُّہٗ کے معنے ہوں
Page 116
گے.یااُسے مٹی میں دبادے.گاڑدے.تفسیر.یعنی باوجود پدری محبت کے اس تذبذب میں پڑجاتاہے کہ ذلت برداشت کرکے لڑکی کو زندہ رہنے دے یااس بے چاری کو زندہ درگورکردے.لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج سارے عرب میں نہ تھا اس بارہ میں یہ امر یادرکھنا چاہیے کہ عام طور پر لوگوں کو یہ غلطی لگی ہو ئی ہے کہ لڑکیوں کو زندہ درگو ر کرنے کارواج عربوں میں عام تھا.لیکن یہ بات نہیں.اگر ایساہوتاتوپھر ان کے ملک میں لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہوجانی چاہیے تھی.اصل بات یہ ہے کہ بے شک لڑکی کی پیدائش کوتوعرب کے سارے ملک میں ہی براسمجھاجاتاتھا مگران کو زندہ دفن کرنے کارواج عملاً صرف بعض بڑے بڑے اورمتکبر لوگوں میں تھا.لڑکی کی پیدائش کو براسمجھنااوربات ہے اوراسے زندہ درگورکردینا اور.آج تک لو گ لڑکی کی پیدائش کو عموماً براسمجھتے ہیں اِلَّامَاشاء اللہ.مگرانہیں مارتے چند ہی لوگ ہیں.لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کے ذکر میں صرف قوم کے عمائدین کا ذکر ہے عرب میں بھی یہ فعل مکہ میں بہت ہی کم ہوتاتھا.عام طورپر ان قبائل میں جواپنے آپ کو بہت بڑاسمجھتے تھے یہ طریق رائج تھا او روہ بھی بعض بڑے لوگوں میں.پس ا س جگہ عام رسم کا ذکرنہیں بلکہ قوم کے عمائدین کے ایسے فعل کو بیان کیاگیا ہے جس کی نقل گوساری قوم نہیں کرتی تھی مگر اسے ایک عزت کافعل سب سمجھتے ہیں.(تاریخ الاسلام السیاسی تالیف ڈاکٹر ابراہیم حسن جلد اول ص ۶۵ مکتبۃ الحفظۃ المصریۃ بالقاہرۃ) اَلَاسَآئَ مَایَحْکُمُوْنَ کا مطلب اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ میں بتایا ہے کہ وہ جوبیٹیوں کو براسمجھتے ہیں ان کا یہ فعل نہایت ہی گندہ ہے اگر بیٹیاں نہ ہوتیں تووہ کس طرح پیدا ہوتے.اوراگر آئندہ بیٹیاں نہ ہوںتوان کے بیٹوں کی نسل کس طرح چلے.قرآن مجید کے ذریعہ عورتوں کی عزت کا قیام قرآ ن کریم نے شروع سے ہی عورتوں کی عزت کوقائم کیا ہے اوران کے حق کو تسلیم کیا ہے.مگر باوجوداس کے اب تک یہ کہاجاتاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر ظلم کیا.بھلاوہ کون سی کتاب ہے جس میں ابتداء ہی سے عورت کے حقوق کی حفاظت اورنگہداشت کی گئی ہو.وہ صرف اورصرف قرآن مجید ہی ہے.
Page 117
لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ١ۚ وَ لِلّٰهِ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی حالت بری ہے.اور(ہر)اعلیٰ صفت(اورشان)اللہ(تعالیٰ)ہی الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ١ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُؒ۰۰۶۱ کی ہے.اور وہی غالب (اور)حکمت والا ہے.حلّ لُغَات.اَلْمَثَلُ.لِلّٰہِ الْمَثَلُ الْاَعْلیٰ اعلیٰ صفت اورشان اللہ ہی کی ہے.اَلْمَثَلُ کے معنے کے لئے دیکھو رعدآیت نمبر ۳۶.اَلْمَثَلُ.اَلشِّبْہُ.مشابہ.اَلنَّظِیْرُ.نظیر.اَلصِّفَۃُ.بیان.اَلْحُجَّۃُ.دلیل.یُقَالُ اَقَامَ لَہٗ مثلًا اَیْ حُـجَّۃً اور اَقَامَ لَہٗ مَثَلًا میں مَثَلًا دلیل کے معنی میں استعمال ہو اہے.اَلْحَدِیْثُ.عام بات.اَلْقَوْلُ السَّائِرُ.ضرب المثل.اَلْاٰیَۃُ.نشان.تفسیر.مثل کے مختلف معنوں میں سے ایک معنے بات کے بھی ہوتے ہیں.مثلاً عرب لوگ کہتے ہیں بَسَطَ لَہٗ مَثَلًا اَیْ حَدِیْثًا(اقرب)فلاں شخص نے اس سے خوب لمبی با ت کی.اس آیت میں مثل کالفظ انہی معنوں میں استعمال ہواہے.اورمطلب آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے منہ سے جب بات نکلتی ہے بری ہی نکلتی ہے اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بتائی جاتی ہے و ہ اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے.یہاں اصل مضمون جس کے بارہ میں سورت نازل ہوئی ہے کھول کربیان کردیاگیا ہے اوربتایا گیاہے کہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ کلام الٰہی کے وجود کے بھی منکر ہوتے ہیں اوراپنی ہدایت کے لئے خود قانون بناناچاہتے ہیں لیکن اس کوشش میں بری طرح ناکام رہتے ہیں اورجوبات کرتے ہیں اُلٹی ہی کرتے ہیں.لیکن جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ سب عیبوں سے پاک ہوتاہے اورسب خوبیوں کاجامع ہوتاہے پھر کلام الٰہی کی ضرورت کایہ لوگ کس طرح انکار کرسکتے ہیں.قرآن مجید کے بیان کا ایک خاص انداز اس جگہ کہا جاسکتا ہے کہ کیوں یوں نہ کہا گیا کہ جو لوگ کلام الٰہی کے منکر ہوتے ہیں وہ غلط باتیں کرتے ہیں.یہ کیوں کہاگیا کہ جولوگ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے غلط باتیں کرتے ہیں.اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کاایک خاص انداز یہ بھی ہے کہ وہ ایسے طریق پر بات کرتا ہے کہ جس نقص کا وہ ذکرکررہاہو اس کے بواعث بھی وہ ساتھ ہی بیان کرتا جاتاہے.اسی انداز کویہاں اختیار کیاگیاہے اوریہ
Page 118
بتایاگیاہے کہ جولوگ کلام الٰہی کی ضرورت کے منکر ہوتے ہیں وہ ایسایوم آخر کے انکار کی وجہ سے کرتے ہیں.ورنہ کوئی شخص جو یوم آخر پر ایمان لاتاہو کلام الٰہی کی ضرورت کا انکارنہیں کرسکتا.کیونکہ ایساشخص انسانی زندگی کاسب سے اہم زمانہ اسی زمانہ کو سمجھے گا جومرنے کے بعد آنے والا ہے اور چونکہ مرنے کے بعد پھر واپس لوٹنے کی کوئی صورت نہیں وہ اُخروی زندگی کی اہمیت کوجانتے ہوئے اس ضرورت کو بھی محسوس کرے گا کہ اس عالم سے واقف ہستی کی طرف سے ہی وہ راہ بتائی جانی چاہیے.جس پرچل کر بعد الموت زندگی اچھی گذا رسکے.اگرصرف اس قدر کہاجاتاکہ جوکلام الٰہی کے منکر ہیں ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں تواس سے یہ مفہوم ادانہ ہوسکتاتھا.صفت عزیز اور حکیم سے یوم آخر کا ثبوت الْعَزِيْزُاور الْحَكِيْمُ کی صفات آخر میں اس لئے رکھی ہیں تااس طرف اشارہ ہو کہ غالب ہی اپنی طاقت کااظہار کرسکتاہے اورالحکیم ہی حکمتوں کو بیان کرسکتاہے اس لئے یقیناً اس کی تعلیم اعلیٰ ہوگی اورانسان کی نجات کاموجب ہوگی.ورنہ جو حکیم نہیں اورعزیز نہیں وہ اول توپُرحکمت کلام نہیں کرسکتااوراگر کوئی بات کرے گاتواس کے پوراکرنے کی اس میں طاقت نہ ہوگی.ان صفات سے یوم آخر کابھی ثبوت پیش کیااوربتایا کہ خدائے حکیم کافعل حکمت سے خالی نہیں ہوسکتااوربغیر یوم آخرت کے انسانی پیدائش ایک بے حکمت فعل رہ جاتی ہے.اسی طرح عزیز خدا کاغلبہ کامل اس دنیا میں نہیں ہوسکتا اس کے لئے یوم آخرکی ضرورت ہے.اگر کہو اس دنیا میں کیوں نہیں ہوسکتا توا س کا جواب صفت حکیم ہے یعنی اسی دنیا میں کامل غلبہ ظاہرہوتو ایمان فضول ہو جاتا ہے.وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ اوراگراللہ (تعالیٰ کی یہ سنت ہوتی کہ وہ)لوگوں کو ان کے (ارتکاب )ظلم پر (فوراً)پکڑ لیتا(اورتوبہ کے لئے مہلت دَآبَّةٍ وَّ لٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى١ۚ فَاِذَا جَآءَ نہ دیتا)تووہ اس (زمین)پرکسی جاندار کو(زندہ )نہ چھوڑتا مگر(اس کی یہ سنت ہے کہ )وہ (اصلاح کے لئے)انہیں اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ۠ سَاعَةً وَّ لَا ایک معیّن وقت تک مہلت دیتا (چلاجاتا)ہے پھر جب ان(کی سزا)کا وقت آجاتاہے تووہ نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ
Page 119
يَسْتَقْدِمُوْنَ۠۰۰۶۲ (کربچ)سکتے ہیں اورنہ (اس سے)آگے نکل (کربچ) سکتے ہیں.حلّ لُغَات.دَآبَّۃٌ دَآبَّۃٌ کے لئے دیکھو نحل آیت نمبر ۵۰.اَجَلٌ اَجَلٌ کے معنے کے لئے دیکھو رعدآیت نمبر۳۹.اَلْاَجَلُکے معنے ہیں مُدَّۃُ الشَّیْءِ.کسی چیز کی مدت.وَوَقْتُہُ الَّذِیْ یَحِلُّ فِیْہِ.کسی امر کی وہ مدت جب جاکر وہ واقعہ ہوتا ہے.(اقرب) السَّاعة.السَّاعَةُکے معنے ہیں اَلْوَقْتُ الْحَاضِرُ.موجودہ وقت.اَلْقِیَامَۃُ.قیامت.وَقِیْلَ الْوَقْتُ الَّذِیْ تَقُوْمُ فِیْہ الْقِیَامَۃُ.اوربعض نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ وہ وقت جبکہ قیامت برپاہوگی.وَعِبَارَۃٌ عَنْ جُزْءٍ قَلِیْلٍ مِنَ النَّہَارِ اَوِاللَّیْلِ:رات یادن کے تھوڑے حصے کو بھی ساعۃ کہتے ہیں.جب یہ کہیں کہ جَلَسْتُ عِنْدَکَ سَاعَۃً مِنَ النَّھَارِ اَوِاللَّیلِ تواس کے معنے ہوتے ہیں.اَیْ وَقْتًا قَلِیْلًامِنْہُ.یعنی میںتمہارے پاس کچھ دیر بیٹھارہا.(اقرب) تفسیر.آیت مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ سے کفار کے ایک شبہ کا ازالہ اس میں کفارکے ایک شبہ کاازالہ کیا ہے جو پہلی آیت سے پیداہوسکتاتھا.اوروہ یہ ہے کہ اگرانسان غلط تعلیم دیتاہے اورخدا کی کلام ہی سے ہدایت ملتی ہے توچاہیے تھا کہ سب کفار ہلاک ہوجاتے مگروہ توہلاک نہیں ہوئے بلکہ دنیا میں کئی قسم کی ترقیاں ان کو ملتی ہیں معلوم ہواکہ وہ بھی کوئی زیادہ غلطی پر نہیں ہیں یایہ کہ وہ بھی حق پر ہیں.اس شبہ کایہ جواب دیا کہ کلام الٰہی کوتوخیر تم نہیں مانتے لیکن بعض امورکو توتم بھی خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف سمجھتے ہو.مثلاً چوری ،ڈاکہ،قتل وغیرہ.کیا ان جرائم کے مرتکب فوراً پکڑ لئے جاتے ہیں.اگرنہیں توا س ڈھیل کودیکھتے ہوئے تم الٰہی کلام کے منکروں پر فوری گرفت نہ آنے کی وجہ سے یہ کس طرح استدلال کرسکتے ہو کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ورنہ اس کے انکارپر فوراً گرفت ہوتی اورکوئی کافر نہ بچتا.فوری سزا نہ آنے کی وجہ پھر اس فوری گرفت نہ ہونے کی وجہ بھی بتائی کہ یہ ڈھیل کاقانون اللہ تعالیٰ نے اس لئے جاری کیاہے کہ اس کے بغیر نسل انسانی چل ہی نہیں سکتی.کیونکہ اگر ہرجرم کی سزامیں انسان کو فوراً تباہ کردیاجاتا تودنیا پر انسان کی نسل کس طرح باقی رہتی.اگر کوئی کہے کہ دنیا میں نیک بھی توہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ بے شک
Page 120
نیک بھی ہوتے ہیں.مگر یہ توضروری نہیں کہ نیکوں کے باپ داداآدم تک سب نیک ہی ہوں.پس اگران کے باپ دادوں کو پکڑاجاتا اوروہ ہلاک کردیئے جاتے توساتھ ہی ان کے وہ نسل بھی غائب ہوجاتی جس نے آئندہ کسی زمانہ میں نیک ہوناتھا.پس اگر ہرگناہ پر اس دنیا میں گرفت کاقانون جاری ہوتومانناپڑے گاکہ دنیا کبھی کی تباہ ہوجانی چاہیے تھی مگرایسانہیں.ہر گناہ کی سزا فوری نہیں ملتی معلوم ہواکہ ہر گناہ کی سزافوراً نہیں ملتی اوریہ مزید ثبوت یوم آخرت کا ہے جہاں جزاسزاکاعمل تکمیل تک پہنچ جائے گا.اگر اس د ن کونہ ماناجائے تو خدا تعالیٰ کا فیصلہ نامکمل رہ جاتاہے.آیت مَا تَرَكَ عَلَيْهَا الخ پر ایک سوال اور اس کا جواب ایک سوا ل اس آیت کے متعلق یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیو ں فرمایاگیا ہے کہ اگر ہرگناہ پراسی دنیا میں گرفت ہوجاتی تو اس دنیا کے پردہ پر کوئی حیوان نہ رہتا.مکلف توانسان ہیں سزاملتی توانسان کوملتی دوسرے حیوان کیوں ہلاک ہوجاتے.اس کا جواب یہ ہے کہ جیساکہ شروع سورۃ میں بیان کیا گیا ہے باقی حیوان انسان ہی کے فائدہ کے لئے پیداکئے گئے ہیں.پس جب انسان ہلاک کردیاجاتا توان کی بھی ضرورت نہ رہتی اورعام قیامت آجاتی.وَ يَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَ تَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اورو ہ اللہ (تعالیٰ)کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے وہ (خوداپنے لئے )ناپسند کرتے ہیں اوران کی اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ١ؕ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ اَنَّهُمْ زبانیں(بڑی جرأت سے کام لے کریہ)جھوٹ بولتی ہیں کہ انہیں بھلائی ملے گی یہ اٹل بات ہے کہ ان کے لئے مُّفْرَطُوْنَ۰۰۶۳ (دوزخ کی )آگ(کاعذاب مقدر)ہے اوریہ کہ انہیں(اس میں )چھوڑ دیاجائے گا.حلّ لُغَات.تَصِفُ تَصِفُ وَصَفَ سے مضارع واحد مؤنث غائب کاصیغہ ہے.اوروَصَفَ الشَّیْ ءَ کے معنے ہیں.نَعَتَہٗ بِمَافیہ وَحَلَّاہٗ.کسی چیز کو پورے طورپر اورعمدہ طریق سے بیان کیا.وَصَفَ الطَّبِیْبُ لِلْمَرِیْضِ:بَیَّنَ لَہٗ مَایَتَدَاوَی بِہٖ.طبیب نے مریض کوعلاج کے لئے دوابتائی (اقرب) پس تَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ
Page 121
الْكَذِبَ کے معنے ہوں گے.ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں.اَلْحُسْنٰی کے معنے کے لئے دیکھو رعد ۱۹.یونس ۲۷.اَلْحُسْنٰی: ضِدُّ السُّواَی.حسنی.سوی.یعنی برائی کے مقابل کا لفظ ہے اور اس کے معنے ہیں اَلْعَاقِبَۃُ الحَسَنَۃُ.اچھا انجام.الظَّفَرُ کامیابی.(اقرب) لَاجَرَمَ کے معنے کے لئے دیکھو ھودآیت نمبر ۲۳و آیت نمبر ۲۴ سورۃھذا.مُفْرَطُوْنَ.اَفْرَطَ سے اسم مفعول مُفْرَطٌ آتاہے اور مُفْرَطُوْنَ اس کی جمع ہے.اَفْرَطَ الْاَمْرَ کے معنی ہیں نَسِیَہٗ.کسی بات کوبھول گیا.تَرَکَہٗ وَخَلَّفَہ.اس کو پیچھے چھوڑ دیا.اَفْرَطَ عَلَیْہِ:حَمّلَہُ مَالَایُطِیْقُ:اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا.وَمَا اَفْرَطْتُ مِنَ الْقَوْمِ اَحَدًا کے معنے ہیں اَیْ مَاتَرَکْتُ میں نے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑا(اقرب)پس اَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَکے معنے ہوں گے.انہیں اس میں چھوڑ دیاجائے گا.تفسیر.اس آیت میں پہلے مضمون کی طرف پھر ایک اوررنگ میں رجوع کیا ہے.فرماتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح یقین رکھتے ہیں کہ ان کاانجام اچھاہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ کی نسبت وہ باتیںمنسوب کرتے ہیں جن کو یہ خود بھی ناپسند کرتے ہیں.جواللہ تعالیٰ کی طرف عیب منسوب کرتے ہیں ان کاانجام کس طرح اچھا ہوسکتا ہے.اَنَّھُمْ مُّفْرَطُوْنَ کا مطلب وَاَنَّھُمْ مُّفْرَطُوْنَ میں یہ بتایاگیا ہے کہ جس طرح انہوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیاہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈال کر چھوڑ دے گااوروہ خبرنہ لے گا.تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ اللہ (تعالیٰ)کی قسم !ہم نے تجھ سے پہلے کی(تمام)امتوں کی طر ف رسول بھیجے تھے پھر انہیں شیطان نے ان کے الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ (بد)اعمال خوبصورت کرکے دکھائے سوآج وہی ان کا آقا(بناہوا)ہے اوران کے لئے (آج )دردناک
Page 122
اَلِيْمٌ۰۰۶۴ عذاب(مقدر)ہے.حلّ لُغَات.اَلْوَلِیُّ.کے معنے ہیںاَلْمُحِبُّ وَالصِّدِیْقُ دوست اورمحبت کرنے والا.اَلنَّصِیْرُمددگار.وَکُلُّ مَنْ وَلِیَ اَمْرَاَحَدٍفَھُوَ وَلِیُّہُ.جس شخص کے قبضہ میں کسی کامعاملہ ہو(اقرب) تفسیر.تَاللہِ کے متعلق دیکھوآیت نمبر ۵۶سورۃ نحل.آیت کامفہو م یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے زمانے میں بھی شیطان نے انبیاء کے مخالفین کویہ تسلی دےکر گمراہ کئے رکھا تھا کہ جو ہم کررہے ہیں اس پرکوئی گرفت نہیں.یہی حال ان کاہے یہ بھی اس قدر غلطیاں کرکے مطمئن بیٹھے ہیں اورجانتے نہیں کہ ایک درد ناک عذاب ان کی طرف بڑھ رہاہے.وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ اورہم نے اس کتاب کو تجھ پر اسی لئے اتاراہے کہ جس (جس )بات کے متعلق انہوں نے (باہم)اختلاف الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ١ۙ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً (پیدا)کرلیا ہے اس(کی اصل حقیقت )کوان پر روشن کرے.اور(نیز )جو(اس پر)ایمان لائیں ان کی لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۰۰۶۵ رہنمائی کے لئے اور(ان پر )رحمت (نازل) کرنے کے لئے.تفسیر.کلام الٰہی کے نزول کی ضرورت یعنی کلام الٰہی کے نزو ل کی ایک اوربھی ضرورت ہے کہ دنیا میں لوگوں میں اخلاقی اورمذہبی امورکے بارہ میںشدید اختلاف پایا جاتا ہے.یہ اختلاف بغیر اس کے کس طرح دورہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک یقینی علم حاصل ہوجائے.پس اس علم کے دینے کے لئے یہ کتاب نازل ہوئی ہے.اس کے سواکون سی تعلیم دنیا کے اختلاف مٹاسکتی ہے.اگردنیا کو معلو م ہوجائے کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تب تو وہ اپنے خیالات کوچھوڑ دے گی.ا س کے بغیر و ہ کس طرح اپنے خیالات کو چھوڑ سکتی ہے.
Page 123
کیونکہ طبعاً ہرشخص اپنے خیالات کو دوسروں کے خیالات پر ترجیح دیتاہے.انبیاء کی بعثت کی ضرورت اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تم کو پہلے نبیوں کے بعد دوسرے نبی کے آنے پراعتراض ہے.دوسرانبی توخود تمہارے اعمال کی وجہ سے آیا ہے تم نے سچائی کو چھوڑ کراختلاف کیوں کیا.تم اختلا ف نہ کرتے توبے شک نبی کی ضرورت نہ ہوتی مگر تم نے مرض توپیداکرلی اب کہتے ہوکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی اختلاف کودورکرنے والے شخص کی آمد کی ضرورت نہیں.مذکورہ بالامضمون پر یہ سوال کیا جاسکتاہے کہ فرض کرولوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ہی عمل کرتے رہتے اوراختلاف نہ کرتے توکیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کامل شریعت یاکامل تعلیم نہ آتی ؟ ا س کا جواب یہ ہے کہ یہ فرضی کلام ہے.حقیقتاً نہ اختلاف کرنے سے لوگوں نے رکناتھا اورنہ اس تعلیم کے آنے میں روک پیداہونی تھی.مگر بفرض محال ایسی صورت ہوتی بھی تواللہ تعالیٰ نے ا س کایہ جواب دیاہے کہ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنَ۠ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا(بنی اسرائیل :۹۶)اگر دنیا میں سب فرشتے ہی فرشتے ہوتے یعنی سب کے سب انسان نیک ہوتے تو ہم ان میں سے ہرایک شخص پر اپنا کلام نازل کرتے یعنی اس صورت میں ایک نبی قوم کی طرف نہ بھیجا جاتا بلکہ سب ہی نبی ہوجاتے اورانکا راورکفر کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا.مگر نہ دنیاسب کی سب نیک بنی نہ خدا تعالیٰ نے نبیوںکے سلسلہ کوبندکیا.هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ میں مضمون کے دوسرے پہلو کو لیا کہ جو اختلاف کرتے ہیں ان کے لئے تیرا یہ کام ہے کہ قرآن کریم کے روسے ان کے اختلاف دور کرے اورجو مومن ہیں ان کے لئے ترقیء مدارج اور رحمت کے حصول کاذریعہ اس قرآن کو بنائے.وَ اللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ اوراللہ (تعالیٰ)نے (ہی)آسمان سے (عمدہ )پانی اتاراہے اوراس کے ذریعہ سے ا س نے تمام زمین کواس کے بَعْدَ مَوْتِهَا١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً مردہ ہوچکنے کے بعد (ازسرنو)زندہ کیا ہے.جولوگ(حق بات کو)سنتے (اوراسے قبول کرنے کے لئے
Page 124
لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَؒ۰۰۶۶ تیارہوتے)ہیں ان کے لئے اس میں یقیناًایک(بہت بڑا)نشان (پایاجاتا)ہے تفسیر.پانی سے مراد کلام الٰہی اس جگہ پانی سے مرادکلام الٰہی ہے.کیونکہ پانی کے نزول کے ذکر کے بعد لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ فرمایا ہے.یعنی ا س پانی کے نزول میں سننے والوں کے لئے نصیحت ہے.مادی پانی کے نزول میں سننے والوں کے لئے نشان نہیں ہوتا.بلکہ دیکھنے والوں یا سمجھنے والوں یاغورکرنےوالوں کے لئے نشان ہوتاہے.سننے کے لفظ سے صاف معلو م ہوتاہے کہ یہاں روحانی پانی یعنی کلام الٰہی مراد ہے اورپہلے نبیوں کی وحیو ں کی طرف توجہ دلائی ہے اوربتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ آسمان سے روحانی پا نی اتار چکا ہے اوراس کے ذریعے سے دنیا کو زندہ کرچکا ہے اگر تم پہلے انبیاء کے حال سنتے توضرو راس صداقت کو تسلیم کرتے.اَحْیَابِہِ الْاَرْضَ سے ھُدًی وَّ رَحْمَةً ہونے کی دلیل اَحْیَابِہِ الْاَرْضَ سے وَھُدًی وَّرَحْمَۃً کی دلیل دی کہ یہ کلام کیوں مسلمانوں کے لئے رحمت اورہدایت ثابت نہ ہوگا جبکہ سا بق کلام مردہ قوموں کو زندہ کرتے چلے آئے ہیں.جو اس وقت ہواوہی اب بھی ہو گا.وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً١ؕ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ اور تمہارے لئے چارپایوںمیں(بھی)یقیناًنصیحت حاصل کرنے کاذریعہ (موجود )ہے(کیاتم دیکھتے نہیں کہ ) بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآىِٕغًا جوکچھ ان کے پیٹوں میں (گند وغیرہ بھرا)ہوتا ہے اس میں سے یعنی گوبر اورخو ن کے درمیا ن سے ہم تمہیں پینے لِّلشّٰرِبِيْنَ۰۰۶۷ کے لئے (پاک اور)صاف دودھ (مہیا کر )دیتے ہیں جو(اس کے )پینے والوں کے لئے خوشگوار (بھی )ہوتا ہے.حلّ لُغَات.اَلْاَنْعَامُ اَلنَّعَمُ: اَلْاِبِلُ وَالشَّاءُ وَقِیْلَ خَاصٌّ بِالْاِبِلِ.نعم کالفظ اونٹ اور بکریوں پر بولاجاتا ہے اوربعض کہتے ہیں کہ یہ صرف اونٹوں پر بولاجاتاہے.وَقَالَ فِی الْمِصْبَاحِ النَّعَمُ:اَلْمَالُ
Page 125
الرَّاعِیْ وَھُوَ جَمْعٌ لَاوَاحِدَ لَہٗ مِنْ لَفْظِہٖ وَاَکْثَرُ مَایَقعُ عَلَی الْابِلِ.اورمصباح میں یو ں لکھاہے کہ نَعَم چرنے والے جانوروں کو کہتے ہیں.اورلفظ نعم جمع ہے.اوراس کے مادہ (ن.ع.م)سے ا س کاکوئی مفرد نہیں (جیسے عربی میں نِسْوَۃٌ کالفظ ہے جس کے معنے عورتوں کے ہیں.اس کامفرد اس کے مادہ میں سے نہیں آتا.ہاں مفرد کے لئے اِمْرَء ۃٌ کالفظ استعمال ہوتاہے )وَقَالَ اَبُوْعُبَیْدٍ اَلنَّعَمُ: الْجَمَالُ فَقَطْ وَیُؤَنَّثُ وَیُذَکَّرُ.اورابو عبید کہتے ہیں کہ نَعَم کالفظ صرف اونٹو ں پر بولاجاتا ہے.اوریہ نراورمادہ دونوں پر استعمال ہوتاہے.اس کی جمع اَنْعَامٌ ہے.وَقِیْلَ النَّعَمُ :اَلْاِبِلُ خَاصَّةً وَالْاَنْعَامٌ ذَوَاتُ الْخُفِّ والظِّلفِ وَھِیَ الاِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ.اوربعض کہتے ہیں کہ نَعَم کالفظ اونٹوں کے لئے خاص ہے لیکن انعام میں اونٹ بھیڑ اورگائے سبھی شامل ہیں.وَقِیْلَ یُطْلَقُ الْاَنْعامُ عَلٰی ھٰذِہِ الثَّلاثَۃِ فَاِذَاانْفَرَدَتْ الْاِبِلُ فَھِی نَعَمٌ.وَاِنِ انْفَرَدَتِ الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ لَمْ تُسَمَّ نَعَمًا اوربعض کے نزدیک انعام کالفظ بھیڑ اونٹ اورگائے کے مجموعہ پر بولاجاتا ہے.اوراگر اونٹوں کو ان سے علیحد ہ کیاجائے تواونٹوں کے لئے نَعَم کا لفظ بولاجائے گامگر صر ف گائے بھیڑ بکریوں کونَعَم نہیں کہیں گے.(اقرب) فَرْثٌ.اَلسِّرْجِیْنُ مَادَامَ فِی الْکَرِشِ.گوبر جب وہ اوجھری میں ہو فرث کہلاتاہے (اقرب) سَائغًا.السَّائِغُ:اَلسَّھْلُ الْمُدْخِلُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.کھانے پینے کی آسانی سے حلق سے اترنے والی اشیا ء سائغ کہلاتی ہیں.(اقرب) تفسیر.انعام میں عبرت یہ فرماکر کہ چارپایوں میں بھی تمہارے لئے عبرت ہے کیالطیف بات بیان فرمائی ہے.چارپائے غذاکے طور پر بھی کام آتے ہیں.ان میں سے دود ھ بھی لیاجاتا ہے ان کا گوشت بھی کھایاجاتاہے.اس کے علاوہ انعام اسبا ب اٹھانے کے بھی کام آتے ہیں.انعام کا بوجھ اٹھانے کے لئے کام میں استعمال ہونا عرب میں زیادہ تراونٹ اس کام آتے تھے کیونکہ وہاں گائے بیل کم ہوتے ہیں.لیکن دوسرے ملکوں میں بیل بھی بوجھ اٹھا کرلے جا نے میں بہت مدد دیتے ہیں.رہ گئیں بکریاں اوربھیڑیں سو بعض پہاڑی ملکوں میں ان سے بھی اسباب اٹھانے کاکام لیا جاتا ہے خصوصاً جبکہ سفراونچے پہاڑوں کا ہو توان جانور وں پر تھوڑاتھوڑ ااسباب لادکر گلّے پالنے والے کرایہ کافائدہ بھی اٹھالیتے ہیں.میں نے کانگڑہ میں دیکھا ہے کہ لاہول کے پہاڑوں پر سے آنے والے گڈریے اپنے اسباب کثرت سے بھیڑوں پر لاد کر لاتے ہیں.سینکڑوں بھیڑوں پر دس دس بیس بیس سیر اسباب لداہواعجیب لطف دیتا ہے.پس سب انعام ہی
Page 126
اسباب اٹھانے کاکام دیتے ہیں.پس عِبْرَۃٌ کالفظ جو عُبُوْرٌسے نکلا ہے جس کے معنے سفر کے بھی ہوتے ہیں.اسے استعمال کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جانوروں سے سفروں میں کام لیتے ہو وہ تم کو اور تمہارے اسباب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتے ہیں مگر ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے.یعنی اپنے ذہنوں کے سفر میں ان سے مدد نہیں لیتے اوران کی حالت پر غور کرکے اس زیر بحث مسئلہ میں جہالت کے ملک سے علم کے ملک کی طرف سفر نہیں کرتے.عِبْرَۃٌ کے معنی عِبْرَۃٌ کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری اُسی کے مشابہ چیز کی طرف ذہن کاانتقال کیا جائے اورپہلی پر قیاس کرکے دوسری کو سمجھاجائے.پس جانوروںکے ذکر میں عبر ۃ کالفظ استعمال فرما کر ایک عجیب پر لطف مضمون پیداکر دیاگیاہے.وہ عبرۃ کیا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیاہے وہ خود ہی اگلے الفاظ میں بیان فرما دی ہے اوروہ یہ ہے کہ چارپائے گھاس پتے کھاتے ہیںجس سے گوبربنتاہے پھر گوبر میں سے ایک حصہ خو ن بنتاہے اوراس خو ن کاایک حصہ دودھ بن جاتاہے جسے انسان مزے لے کر پیتا ہے اوروہ ایسا خالص ہوتاہے کہ کوئی نفاست پسند انسان بھی اس کے پینے میں کراہت محسوس نہیں کرتا.حالانکہ دودھ پہلے خو ن تھا اورخون اس فضلہ سے بنتاہے جو غذاسے جانور کے معدہ میں تیارہوتاہے اوروہاں سے انتڑیوں میں جاکر باریک عروق کے ذریعہ سے دل کی طرف لے جایاجاتاہے جہاں جاتے ہی وہ خون بن جاتا ہے اورخون تھنوں میں آکر دودھ کی شکل اختیار کرلیتا ہے.گھاس پتوں سے دودھ بنانے کے ذکر سے روحانی تعلیم کے صاف کرنے کی طرف اشارہ اس آیت میں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہی گھاس اورپتے جن کو انسان استعمال نہیں کرسکتا جانور کے پیٹ میں جاکر گوبر بنتے ہیں اوراس سے خون بنتاہے اوراس سے دودھ اوروہ دود ھ خالص ہوتا ہے کوئی گندگی اس میں نہیں ہوتی اورپینے میں مزہ دار ہوتاہے.اس گھاس کو انسان اس جانورسے باہر دودھ کی شکل میں تبدیل نہیں کرسکتالیکن اللہ تعالیٰ اس کو لے کر جانور کے ذریعہ سے دودھ بنادیتاہے.اس سے انسانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ وہی فطرتی تعلیم جس پر چل کر انسان یقین کے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا اورہزاروں گند اورنقص اس میں پائے جاتے ہیں.جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی روحانی مشین میں سے گذرتی ہے تومصفّٰی دودھ کی طرح ہوجاتی ہے جس سے کسی قسم کانقصان روحانی صحت کو نہیں پہنچ سکتا بلکہ ہر طرح فائدہ پہنچتاہے.پس جانوروں کے اندرجو دودھ بنتاہے اس سے یہ لوگ کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے اورنہیں سمجھتے کہ انسان کی سچی غذا فطرت کے میلان تب ہی بن سکتے
Page 127
ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو روحانی دودھ کی شکل میں بد ل دے.اوریہ کام انسان خود نہیں کرسکتا.جوگھاس کو دودھ میں تبدیل نہیں کرسکتا وہ فطرت کے اَن گھڑے جذبات کو اعلیٰ تعلیم میں کب تبدیل کرسکتا ہے.اس آیت میں ایک لفظی اشکال اس آیت میں ایک لفظی اشکال بھی ہے اوروہ یہ کہ بطونہٖ میں مفرد کی ضمیر ہے اورماقبل اس کے اَنعام جمع کالفظ ہے.مفسرین نے اس کے دوجواب دیئے ہیں.ایک یہ کہ مفرد کی ضمیر معنیً پھرائی گئی ہے اورمراد یہ ہے کہ جس چیز کاہم نے ذکر کیا ہے.یعنی انعام.اس کے پیٹ میں مذکورہ طریق سے دودھ بنتا ہے گویاضمیر انعام کی طرف نہیں بلکہ مَاذُکِرَ یامَاذَکَرْنَا ہُ کی طرف ہے اورما کی طرف خواہ وہ جمع کے لئے ہو مفرد کی ضمیر پھیر نی جائز ہے.(تفسیر فتح البیان زیر آیت ھذا) مختلف مفسرین کے نزدیک لفظی اشکال کی تاویل دوسری تاویل مفسرین یہ کرتے ہیں کہ کبھی جمع کالفظ بول کر اس کی طرف مفرد ضمیر اس اشارہ کے لئے لاتے ہیں کہ اس کے ہرفرد یااس کی ہرقسم کے ساتھ یہ معاملہ گذرتا ہے.یہ دونوں تاویلات درست ہیں اورعربی قواعد کے مطابق ہیں.سائینس کی موجودہ تحقیق دودھ بننے کے متعلق قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہے یہ آیت اس امر پر بھی شاہد ہے کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا دنیاکاخالق بھی ہے کیونکہ اس میں دودھ کے پیدا ہونے کاوہ طریق بتایاگیا ہے جو اس وقت دنیا کو معلوم نہ تھا اوربعدمیں دریافت ہواہے.اوروہ یہ کہ غذامعدہ میں سے انتڑیوں میں آتی ہے اوراس سے فرث تیارہوتاہے اس فرث سے ایک ماد ہ خون بن جاتاہے اوراس خون سے دودھ بنتاہے.یہی وہ حقیقت ہے جو نزول قرآن کے بعد کی تحقیق سے ثابت ہوئی ہے.چنانچہ بعد کے مفسرین نے ابتدائی مفسرین کی غلطی کو پیش کر کے ظاہر کیا ہے کہ درحقیقت فرث سے خون اورخون سے لبن بنتاہے.مگر جو تشریح انہوں نے بیان کی ہے وہ بھی پوری طرح سائنس کے مطابق نہیں.لیکن قرآن کریم کے الفاظ سائنس کی موجود ہ تحقیق کے بالکل مطابق ہیں.اوروہ یہ ہے کہ غذامعدہ سے انتڑیوں میں جاتی ہے وہاں سے اس کامنہضم لطیف حصہ بعض عروق کے ذریعہ سے ایک حصہ سیدھا دل تک جاتا ہے اور وریدوں میں گرکرفوراً خو ن بن جاتا ہے اور ایک اور لطیف حصہ معدہ سے براہ راست جگر میں جا کر وہاں سے وریدوں کے ذریعے دل میں گر کر خون بن جاتا ہے پھر یہ خون جب تھنوں کے قریب جاتا ہے تووہاںاللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیداکئے ہیں کہ وہ خون وہاں جاکردودھ بن جاتاہے.پرانے زمانہ کے لوگوں کی دودھ کے بننے کے طریقہ سے ناواقفیت اس حقیقت سے پرانے زمانہ کے لوگ ایسے ناآشنا تھے کہ مفسرین نے اس آیت کے معنے کرنے میںسخت مشکلات محسوس کی ہیں اوررائج الوقت
Page 128
خیالات کے مطابق یہ سمجھا ہے کہ شاید فرث اورخون کے بننے کے درمیان کوئی تغیر ایساہوتاہے جس سے دودھ بنتاہے.چنانچہ صاحب کشاف لکھتے ہیں کہ جب غذاجانورکے معدہ میں جاتی ہے تواس کا نچلا حصہ گوبر بن جاتاہے اور درمیانی حصہ دودھ بن جاتاہے اوراوپر کا حصہ خون بن جاتاہے (کشاف زیر آیت ھذا).حالانکہ آیت صاف بتارہی ہے کہ فرث اورخون میں سے ہوتے ہو ئے دودھ کاماد ہ آتاہے یعنی پہلے فرث کی حالت ہوتی ہے پھر خون کی پھر دودھ کی.اوران پہلی دوچیزوں میں سے کسی کو بھی انسان خوشی سے کھانے کوتیار نہیں ہوتا.نہ گوبر کھانے پر راضی ہو سکتاہے اورنہ خو ن پینے پر خوشی سے تیار ہو سکتا ہے.لیکن جب وہی خون دودھ بن جاتا ہے تواسے خو ب مزے لے کر پیتا ہے اوراس میں فرث کی گندگی اوراورخون کے زہروں میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا.اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی تھوڑی سی مقدار میں بھی دود ھ نہیں بناسکتا.ممکن ہے کسی وقت لو گ کچھ دودھ بھی بنالیں.لیکن ا س طرح ساری دنیا کو غذا نہیں پہنچا سکتے.یو ں تولوگ گیسوں سے پانی بھی بنالیتے ہیں.لیکن وہ چند قطر ے پانی کے بادلوں کاکام نہیں دے سکتے.اسی طرح اگر کسی وقت کوئی شخص گھاس پات سے دودھ بھی بنالے توتعجب نہیں.مگر دنیاکو غذادینے کاکام پھر بھی جانوروں کے سپرد ہی رہے گاجس طرح پانی مہیا کرنے کاکام بادلوں کے سپر د ہے.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انسان غذاکو گندہ توکرسکتاہے لیکن اس سے دودھ نہیں بنا سکتا.اسی طرح انسان انبیاء کی تعلیم کو لے کر خراب تو کردیتے ہیں لیکن انسان دماغوں میں پائی جانےوالی غیر مصفّٰے فطرتی صداقتوں کو مصفّٰے اوراعلیٰ روحانی تعلیم نہیں بناسکتے.وَ مِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَ الْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ اورکھجوروں کے پھلو ں اورانگوروں سے (بھی کہ )جن سے تم شراب (بھی )بناتے ہو اوراچھا رزق( بھی) جولوگ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۰۰۶۸ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے اس میں یقیناً ایک (بڑا)نشان (پایاجاتا)ہے.حلّ لُغَات.اَلنَّخِیْلُ النَّخِیْلُ نَخْلٌ کی جمع ہے اور یہ مؤنث استعمال ہوتاہے.لیکن نَخْلٌ کالفظ مؤنث مذکردونوں طرح استعمال ہوتاہے اس کے معنے ہیںکھجورکے درخت.(اقرب)
Page 129
اَلْاَعْنَابُ.اَ لْاَعْنَابُ عِنَبٌ کی جمع ہے اورعِنَبٌ کے معنے ہیں ثَمْرُالْکَرَمِ وَھُوَ طَرَیٌّ.فَاِذَایَبِسَ فَھُوَ الزَّبِیْبُ یعنی عنب تازہ انگوروں کو کہتے ہیں.جب وہ خشک ہوجائیں تووہ زبیب (منقّہ )کہلاتے ہیں.(اقرب) سَکَرًا:اَلْخَمْرُ.شراب.نَبِیْذٌ یُتّخَذُ مِنَ التَّمْرِ وَالْکَشُوْثِ.کھجوروں کارس.کُلُّ مَا یُسْکَرُ.ہر نشہ آور چیز.الْخَلُّ.سرکہ.اَلطَّعَامُ.کھانا.(اقرب) تفسیر.مفسرین کے نزدیک سکر کے معنی شراب کے اس آیت میں بعض مفسرین نے سکر کے معنے شراب کے کئے ہیں.پھر ان کو یہ مشکل پڑی ہے کہ اس آیت میں سکر کوتواللہ تعالیٰ انعام کے طورپر ذکر فرمارہا ہے حالانکہ شراب ناجائزہے.اس پر انہوں نے یہ تاویل کی ہے کہ یہ آیت اس وقت کی نازل شدہ ہے جبکہ شراب جائز تھی.اوریہ جواب دے کر انہوں نے اس آیت کو منسوخ قرار دے دیا ہے(تفسیر القرطبی زیر آیت ھذا).بعض لوگوں نے اس مشکل کومدنظر رکھتے ہوئے سکر سے کھانا مراد لیا ہے.ان معنوں پر دوسرے علماء نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگریہ معنے ہوں توآیت میں تکرار واقع ہوجائے گا.کیونکہ آگے وَرِزْقًاحَسَنًا بھی بیان فرمایا ہے.اس کاانہوں نے یہ جواب دیاہے کہ سکر کے لفظ میں طاقت مدنظررکھی ہے اوررزق میں غذائیت مد نظررکھی ہے.(تفسیر البغوی زیر آیت ھذا).یہ سب مشکل ان کو اس لئے پڑی ہے کہ انہوں نے جواز اورعدم جواز کامسئلہ اس جگہ سے نکالنا چاہاہے.تَتَّخِذُوْنَ مِنْہُ سَکَرًا کا مطلب حالانکہ خدا تعالیٰ اس جگہ بات ہی یہ بتاناچاہتاہے کہ بسا اوقات ہماری پیداکردہ طیّب چیزیں جب تم تصرّف کرتے ہو تواسے گندہ کردیتے ہو.وہی چیز جوتازہ ہونے کی حالت میں پاک ہوتی ہے جب تم اس میں تغیر کرتے ہو توکیسی گندی ہوجاتی ہے.اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.اِن الفاظ سے اس طرف اشار ہ کیا کہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جس چیز کو جس غرض سے بناتا ہے اس میں تغیر کرنا اس کی اصلاح کا موجب نہیں ہوتابلکہ خراب کرنے کاموجب ہوتاہے.پس نہ توانسان خود روحانی تعلیم بناسکتاہے نہ اسے یہ اختیارہے کہ خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم میں کسی قسم کادخل دے اوراسے اس مقصد سے پھرادے جس کے لئے وہ نازل ہوئی ہے ورنہ ضرورخرابی پیداہوجائے گی.
Page 130
وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ اورتیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف (بھی )وحی کی (ہوئی)ہے کہ توپہاڑوں میں اوردرختوں میں اورجو (انسان بُيُوْتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُوْنَۙ۰۰۶۹ انگوروں وغیرہ کے لئے )ٹیک بناتے ہیں ان میں (اپنے )گھر بنا.تفسیر.وحی الٰہی کی ضرورت کے متعلق تیسری مثال وحی الٰہی کی ضرورت کے متعلق یہ تیسری مثال بیان فرمائی ہے اوراس میں پہلی دومثالوںسے بھی زیادہ وضاحت ہے.یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے نحل یعنی شہد کی مکھی کی طرف بھی اس کے ظرف کے مطابق ایک وحی کی ہے اوروہ وحی یہ ہے کہ پہاڑوں پریادرختوں پر یاعرشو ں پر گھر بنا.یہ وحی استعداد باطنی ہے جو شہد کی مکھی میں پیداکی گئی ہے.تمام کائنات کا کارخانہ وحی الٰہی پر چل رہا ہے اوراس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات کا کارخانہ وحی الٰہی پر چل رہاہے.کسی پر وحی خفی نازل ہوتی ہے کسی پر وحی جلی.مگر بہرحال سب کارخانہ وحی پر چل رہاہے یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں اورمیلانوں پر چل کر ہی ہر چیز اپنا صحیح فرض اداکرتی ہے.اگراس طریق کو چھوڑ دے توکبھی اپنا فرض اچھی طرح ادانہ کرسکے.خدا تعالیٰ کی وحی کی وسعت اس آیت سے معلوم ہوتاہے کہ خدا کی وحی بہت وسیع ہے.بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں آسکتی(محمدیہ پاکٹ بک از مولانا عبد اللہ صاحب امرتسری ص ۶۱۴) حالانکہ اس آیت سے جانوروں کو بھی وحی ثابت ہوتی ہے.اس وحی سے Instinct یعنی طبعی میلانوں کی طرف اشارہ ہے.اس قسم کی وحی عارضی طورپر انسان کوبھی ہوتی ہے.بعض دفعہ یکدم ا س کو کوئی خیال آتاہے جواس کے لئے بہت مفید ہوتاہے.دنیا کے تمام موجد یہی کہتے ہیں کہ اکثرایجادوں کاخیا ل ان کے دل میں یکدم پیداہوایاایجاد کا خیال توعلمی تحقیق کے سلسلہ میں پیداہوالیکن کئی درمیانی مشکلات کاحل ایک فوری ذہنی لہرکے پیدا ہونے سے حاصل ہوا.ایڈیسن جو سب سے بڑاموجد ہے.اس نے اپنے متعلق صا ف لکھا ہے کہ میں نے ایک ہزارایجاد کی ہے ان میں سے سب سے بڑی ایجادیں ایک فوری خیال کی بناء پر ہوئی ہیں.درحقیقت یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفی لوگ
Page 131
الہا م کے نام سے موسوم کرتے ہیں.جانوروں کی تحقیقات میں سے شہد کی مکھی اورچیونٹی کی تحقیقات بہت وسیع ہوئی ہے.اس تحقیقات نے یہ ثابت کیا ہے کہ چیونٹیوں میں بہت بڑابھاری نظام ہوتاہے.یہ ہاتھوںسے بات کرتی ہے.انسان کی طرح اپنی لاش کی حفاظت کرتی ہے غلے کاڈھیر رکھتی ہے.سردی اورگرمی کے مکانات علیحدہ علیحدہ رکھتی ہے.چوبارے بناتی ہے.ایک قسم کاکیڑاہے جس میں سے ایک مادہ نکلتاہے جو چیونٹی کے لئے دودھ کاکام دیتا ہے ان کیڑوں کو یہ جمع کرکے اپنے گھروں میں رکھتی ہیں.اوران کی غذاکاخیال رکھتی ہیں اورجب غلہ میں کمی ہوتوتجربہ سے معلوم ہواہے کہ وہ ان کیڑوں کو پہلے غذادیتی ہیں.پھر بچ رہے توخود کھاتی ہیں.ان میںلڑائیاں بھی ہوتی ہیں.صلح بھی ہوتی ہے.غرض ایک وسیع نظام ان میں پایا جاتا ہے(The Book of Knowledge under word Ant).یہ سب ایک قسم کی وحی خفی کے نتیجہ میں ہے.شہد کی مکھیوں کا نظام اور اس کے ذکر کی وجہ اسی طرح نحل کا بھی بڑاعظیم الشان نظام ہے.بعض ماہروں کاخیال ہے کہ انسانوں کے نظام سے ان کانظام بہتر ہوتاہے.ان کا احساس بعض باتوں میں انسان سے زیادہ ہوتا ہے.ان کے ہرچھتہ میں ایک ملکہ ہوتی ہے.سب مکھیا ں اس کی پیروی کرتی ہیں.ان کی نسلیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں انسانوں کی طرح سب مل کرنہیں رہتیں.جب نئی ملکہ پیداہوتی ہے توپرانی مکھیا ںا س کومارناچاہتی ہیں توساری نئی جوان مکھیاں اس کاپہرہ دیتی ہیں اورمل کر اس کی حفاظت کرتی ہیں وہ ملکہ بڑی ہوکر اپنے ساتھیو ں سمیت علیحدہ چھتہ بناتی ہے.پھر ملکہ لڑائی کرکے یاتوپہلی بڑی مکھیوں کو پہلے چھتہ سے نکال دیتی ہے یا شکست کھا کر دوسری جگہ پر چلی جاتی ہے.ان کے نظام کی اوربھی تفصیلات ہیں جو حیرت انگیز ہیں(The Book of Knowledge under word Ant).خدا تعالیٰ نے نحل کے ذکر کو اس لئے چنا ہے کہ یہ معلوم ہوکہ ایک بالاہستی ہے جس نے اسے یہ علم دیا ہے اوراس کو ایسانظام دیاہے جوخود اس کا سوچاہوانہیں ہے.نیز اس مثال کو اس لئے چنا ہے کہ شہد کی مکھی کانظام معمولی غور سے نظر آجاتاہے.اوراس لئے بھی کہ ا س سے ایک ایسی غذاپیداہوتی ہے جسے انسان نے بہترین سمجھا ہے.اس نظام کااس میں پایاجانا یہ بتاتا ہے کہ اس میں عقل ہے.مگراس کاایک ہی حالت میں رہنا اورترقی نہ کرسکنا یہ بتاتا ہے کہ وہ نظام اس کو کسی اورہستی نے دیا ہے اورباہر سے آیا ہے اس نے خود وہ نظام تیار نہیں کیا.آیت اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًاسے انسانوں کے مختلف درجہ میں مورد وحی ہونے کی طرف اشارہ اس آیت میں اس طر ف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ نحل یعنی شہد کی مکھیا ں بھی مختلف قسم کی ہیں بعض
Page 132
پہاڑوں میں چھتے بناتی ہیں ،بعض میدان کے درختوں پر اوربعض گھروں یا ان عرشوں پر جو انگور وغیرہ کے لئے تیار کئے جاتے ہیں.اس سے اس طرف اشار ہ کیا ہے کہ انسانوں میں سے مَوردِ وحی بھی ایک سے نہیں ہوتے.بعض کا مقام پہاڑ پر ہوتاہے بعض کادرخت پر اوربعض کاچھتوں اورعرشوں پر.یعنی بعض بہت اونچے مقام کے ہوتے ہیں بعض ان سے ادنیٰ اوربعض ان سے ادنیٰ.اس میں گویا اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے جو آیت تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَابَعْضَہُمْ عَلیٰ بَعْضٍ(البقرة:۲۵۴)میں بیان کیاگیا ہے.ثُمَّ كُلِيْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا١ؕ پھر ہرقسم کے پھلوں میں سے (تھوڑاتھوڑالےکر )کھااوراپنے رب کے (بتائے ہوئے )طریقوں پر جو(تیرے لئے ) يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ آسان (کئے گئے )ہیں چل.ان(مکھیوں )کے پیٹوں سے (تمہارے )پینے کی ایک (لطیف )چیز نکلتی ہے جو شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً مختلف رنگوں کی ہوتی ہے (اور)اس میں لوگوں کے لئے شفاء (کی خاصیت رکھی گئی )ہے.جولوگ سوچ (اورفکر ) لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۠۰۰۷۰ سے کام لیتے ہیں ان کے لئے اس میں یقیناً کئی نشان(پائے جاتے)ہیں.حلّ لُغَات.اُسْلُکِیْ :اُسْلُکِیْ سَلَکَ سے امر مؤنث مخاطب واحد کاصیغہ ہے.اورسَلَکَ الْمَکَانَ سَلْکًاکے معنے ہیں :دَخَلَ فِیْہِ.وَکَذَاسَلَکَ الطَّرِیْقَ دَخَلَہٗ سَارَفِیْہِ مُتَّبِعًا اِیَّاہُ.کسی جگہ میں داخل ہوا.یاکسی راستہ پر چلا.اس سے اسم فاعل سَالِکٌ آتاہے (اقرب)مزید تشریح کے لئے دیکھو حجرآیت نمبر ۱۴.نَسْلُکُ سَلَکَ سے مضارع جمع متکلم کاصیغہ ہے.اورسَلَکَ الْمَکَانَ سَلْکًا وَسُلُوْکًا کے معنی ہیں دَخَل فِیْہِ کسی جگہ میں داخل ہوااوراس کے اندر گیا سَلَکَ الطَّرِیْقَ اَیْ دَخَلَہٗ وَسارَفِیْہِ مُتَّبِعًااِیَّاہُ.فَھُوَ سَالِکٌ.اورسَلَکَ الطَّرِیْقَ کے معنی ہیں.راستہ اختیار کرکے اس پر چل پڑااوراس سے اسم فاعل سَالِکٌ (یعنی
Page 134
دے.جب وہ اپنی فطرت کو پاک رکھے اوراس وحی پر عمل کرے جو وحی خفی کے رنگ میں ہرانسان بلکہ ہر مخلوق پر نازل ہوتی ہے.توپھر اللہ تعالیٰ اس پر وہ وحی نازل کرتاہے جوشہد کی مانند ہوتی ہے.یعنی خالص ہوتی ہے اوراس میں بنی نوع انسان کے لئے شفاء کی خاصیت ہوتی ہے.یعنی انسانی کمزوریوں کو دورکرکے انسان کو کامل بنادیتی ہے.اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً میں وحی الٰہی کے بغیر کسی کام کے نہ چل سکنے کی طرف اشارہ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۠.اس میں اس طر ف اشارہ کیاگیاہے کہ بغیر وحی الٰہی کے دنیا میں کوئی کام نہیں چلتا.جوانسان کہتاہے کہ میں خود ہدایت کاکام کرلوں گا وہ غلطی پر ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر خاص زوردیاہے.آپ فرماتے ہیں کہ انسانی کوشش دنیوی امورمیں بہ منزلہ دعا کے ہے اوراس کے نتیجہ میں انسان کے ذہن میں جو تدبیرآتی ہے وہ بھی وحی ہے.غرض مکھی کی مثال سے یہ بتایا ہے کہ کلام الٰہی کے بغیر کامیاب زندگی ناممکن ہے حتیٰ کہ جانور بھی وحی کے محتاج ہیں اوران پر ایک قسم کی وحی نازل ہوتی ہے جس کی نمایاں مثال شہدکی مکھی میں پائی جاتی ہے.پس جبکہ موجودات کے ہر طبقہ کے لئے خدا نے وحی نازل کی ہے حالانکہ ان کی زندگی محدود اورعقل مختصرہےتوانسان جس کی زندگی کااثر اگلے جہان پر بھی پڑتا ہے اس کانظام بغیر وحی کے کس طرح چل سکتاہے.کلام الٰہی بھی شہد کی طرح شفاء کی تاثیر رکھتا ہے قرآن کریم کے متعلق متعدد جگہ وہی الفاظ آئے ہیں جو شہد کے بارہ میں اس آیت میں آئے ہیں اوران سے یہ بتایا ہے کہ یہ کلام اپنے اندروہی خاصیت رکھتاہے جووحی کے نتیجہ میں پیداہوتی ہے یعنی شفاء کی تاثیر.چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۹ میں فرماتا ہے وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ(آیت :۸۳).سورۃ یونس رکوع ۶ میں فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ(آیت :۵۸).پھر حٰم سجدہ رکوع ۵ میں فرماتا ہے قُلْ ھُوَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ھُدًی وَّشِفَآءٌ(آیت :۴۵).وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ١ۙ۫ وَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اوراللہ(تعالیٰ)نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہاری روحیں قبض کرتاہے اور تم میں سے بعض(بعض آدمی ) اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا١ؕ اِنَّ اللّٰهَ ایساہوتاہے کہ وہ عمر کی بدترین حالت کی طرف لوٹادیاجاتاہے جس کے نتیجہ میں وہ علم (والاہونے )کے
Page 135
عَلِيْمٌ قَدِيْرٌؒ۰۰۷۱ بعد(پھر)بے علم ہو جاتا ہے.اللہ (تعالیٰ)یقیناً بہت جاننے والا (اور)ہربات پر پورا(پورا)قادرہے.حلّ لُغَات.اَرْذَلِ الْعُمُرِ اَرْذَلُ کے معنے ہیں اَلدُّوْنُ فِیْ مَنْظَرِہِ وَ حَالَاتِہِ.اپنے حالات اور منظر میں حقیر.اَلرَّدِّیُ مِنْ کلِّ شَیْءٍ.ہرچیز کا ردّی حصہ.اَرَذَلُ الْعُمُرِ.اٰخِرُہُ فِیْ حَالِ الْکِبَرِ وَالْعَجْزِ.بڑھاپے اورکمزوری میں عمر کاآخری حصہ.عمر کی بدترین حالت (اقرب) پس وَمِنْکُمْ مَّنْ یُّرَدُّ اِلیٰ اَرْذَلِ الْعُمُرِ کے معنے ہوں گے کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جوعمر کی بدترین حالت کی طر ف لوٹادئے جاتے ہیں.تفسیر.مَنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِکا مطلب پچھلے رکوع میں تو اس با ت کا ذکر تھا کہ تمہارے معبود کلام الٰہی نہیں بناسکتے.اس رکو ع میں اس بات کو واضح کیاگیا ہے کہ تم خود بھی کلام نہیں بناسکتے.اب اسی سلسلہ میں ایک عام بات بیان فرمائی کہ کامل کلام تووہ بناسکتا ہے جس کے قبضہ میں پیدائش اورموت کا اختیار ہو.پھر اپنی عقل پر بھی اُسے قبضہ حاصل ہو.پس انسان کلام تیار نہیں کرسکتا.کیونکہ نہ اس کے قبضہ میں پیدائش ہے کہ وہ اپنی تعلیم کے مطابق خاصیتیں دوسرے انسانوں میں رکھ دے نہ اس کے قبضہ میں موت ہے کہ وہ بعد الموت زندگی کے سامان پیداکرسکے.نہ اس کے قبضہ میں عقل ہے کہ وہ ایسے وجود بنی نوع انسان کی تعلیم کے لئے مقرر کرسکے جن کی عقل ہمیشہ سلامت رہے.کئی حکومتیں بہترین دماغ کے انسان چن کر پروفیسر مقرر کرتی ہیں لیکن وہ بوڑھے ہوکر اُلٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں.اب یہ فرق کو ن کرے کہ کس وقت سےان کے دما غ میں فتور شروع ہواہے کہ اس وقت کی باتوں کو ردّی قرار دے.پس کئی شاگرد ایسے ضعیف دماغ کی باتوں کو صحیح سمجھ کر گمراہ ہوجاتے ہیں.پس کلام ہدایت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آسکتاہے.کیونکہ وہی انسان کاپیداکرنے والا ہےاور اس کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے وہی وفات دینے والا ہے اوربعدالموت اس کی رہنمائی کافرض اداکرسکتا ہے اُسی کے قبضہ میں انسانی عقل ہے.پس وہ جن لوگوں کو اس وحی کے کام پر مقررکرتا ہے ان کی عقلوں کی صحت کابھی ضامن ہوتاہے.کوئی نبی ارذل العمر تک نہیں پہنچا سوچنے والوں کے لئے یہ ایک بہت بڑانشان ہے کہ آج تک کو ئی نبی دنیا میں نہیں گذراجو ارذل العمر تک پہنچا ہو اورجس کی نسبت یہ کہا جاسکے کہ فلاں وقت دماغی کمزوری کی وجہ سے اس کی باتوں کااعتبار نہیں رہاتھا.کیا سینکڑوں نبیوں میں سے جن کو دنیا جانتی ہے ایک بھی ایسی مثال کا نہ ملنا اس امر کاثبوت نہیں کہ ان کو بھیجنے والا عقل انسانی کامالک ہے.اس لئے اس نے جن کو اپنے بندوں کی تعلیم پر مقرر کیا ان کی عقل کی
Page 136
بھی خود ہی حفاظت کی.قو می زندگی کو لیا جائے تواس آیت میں یہ اشار ہ ہے کہ قوموں پر بھی بڑھاپاآتاہے اوروہ علم کو بھلا بیٹھتی ہیں.اس وقت ایک نئی نسل کی ضرورت ہوتی ہے جن کو خدا تعالیٰ پھر نئے سرے سے اپنی وحی کے ذریعے سے تعلیم دے.اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ کہہ کر اس طرف اشار ہ کیا کہ جس کاعلم قائم رہتاہے اورجوقدرت سے کام کرسکتا ہے ، الہام نازل کر نا اسی کاکام ہے.وَ اللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ١ۚ فَمَا الَّذِيْنَ اوراللہ (تعالیٰ)نے رزق میں (بھی تو)تم میں سے بعض کو بعض سے بڑھا یا (ہوا)ہے.پھر جن لوگوں کو فضیلت دی فُضِّلُوْا بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ گئی ہے وہ اپنا (مقبوضہ)رزق(کسی صورت میں بھی تو)ان کی طرف جن پر ان کے داہنے ہاتھ قابض ہیں لوٹانے فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ١ؕ اَفَبِنِعْمَةِ والے نہیں تاوہ اس میں برابر(کے حصہ دار)ہوجائیں.پھر کیا وہ(اس حقیقت کے جاننے کے باوجود) اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ۰۰۷۲ اللہ (تعالیٰ) کی نعمت کا انکار کرتے ہیں.حلّ لُغَات.عَلیٰ مَامَلَکَتْ اَیْمَانُھُمْ ھُوَمَلَکَۃُ یَمِیْنِیْ کے معنے ہیں.اَمْلِکُہُ وَأَقْدِرُعَلَیْہِ.کہ میں اس کامالک ہوں اوراس پرپوراقابو رکھتا ہوں (اقرب)پس عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ کے معنے ہوں گے جن پر ان کے داہنے ہاتھ قابض ہیں.نِعْمَۃ نِعْمَۃٌکے لئے دیکھو سور ۃ ہذا آیت نمبر ۵۴.یَجْحَدُوْنَ یَجْحَدُوْنَ جَحَدَ سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اورجَحَدَ حَقَّہٗ اور بِحَقِّہِ کے معنے ہیں.اَنْکَرَہُ مَعَ عِلْمِہٖ بِہِ.اس نے جان بوجھ کر کسی کے حق کاانکارکردیا.کَفَرَ بِہٖ اس کا انکار کیا.کَذَّبَہٗ.اس کو
Page 137
جھٹلایا.(اقرب)پس یَجْحَدُوْنَ کے معنے ہوں گےکہ اللہ کی نعمتوں کاجان بوجھ کرانکار کرتے ہیں.تفسیر.اس آیت میں الہام الٰہی کے نزول کی دلیل اس آیت میں الہام کی ایک اورزبردست دلیل دی ہے اوروہ یہ کہ الہام الٰہی صرف عقائد کی اصلاح ہی نہیں کرتا.بلکہ اس کے علاوہ اس کے ذریعہ سے دنیاوی حکومتوں کے توازن کی بھی اصلاح کی جاتی ہے.چنانچہ فرماتا ہے کہ ہرزمانہ میں اللہ تعالیٰ کا بعض افراد یابعض قوموں پر فضل نازل ہوجا تا ہے اوروہ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں.یہاں تک توعام قانون ہے اوراگرایسے لوگ انصاف سے کام لیں اور کسی کی حق تلفی نہ کریں توقابل اعتراض بات نہیں.لیکن ہمیشہ ہوتایہ ہے کہ جن لو گوں کے اختیار میں دنیا آتی ہے وہ کسی صورت میں ان لو گوں کے ساتھ جو ان کے غلام یا بمنزلہ غلام ہوں ان اختیارات کو تقسیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے جو انہیں حاصل ہوچکے ہوں.ان کے قبضہ سے دنیا کو نکال کر عزت اوررتبہ کو لیاقت اورقابلیت اوربنی نوع انسان کی مساوات کی بنیاد پر رکھنے کاصرف اورصرف ایک علاج ہوتاہے اوروہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی ارسال فرماکر پھر بنی نوع انسان کو ان کے حقوق واپس دلائے.جولوگ ملکوں اورحکومتوں کی باگ پر قابض ہوجاتے ہیں ان کا بڑابہانہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا کا انتظا م لائق آدمیوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے.اوروہ بعض خاندانوں اورگھرانوںکو لیاقت کے لئے مخصوص کرلیتے ہیں اوربادشاہتیں قائم ہوجاتی ہیں.بعض خاندان حکومت کرنے کے اہل قرار دے دئے جاتے ہیں اورعوام الناس سے نہ کوئی رائے لیتا ہے نہ ان کا انتظام میں کوئی دخل ہوتاہے.اس کے علاوہ کچھ حقوق انسانوں کے مذہبی لیڈر،پیر اورکاہن چھین لیتے ہیں.دین کو پنڈتوں،مولویو ںاورپادریوں کی جائداد قرار دے لیا جاتاہے.نہ عوام کو دین سے واقف رکھا جاتا ہے نہ انہیں اس کے متعلق دلچسپی لینے کاموقعہ دیاجاتاہے.بس یہ خیا ل کر لیا جاتاہے کہ ان کاکام صرف مذہبی پیشوائوں کے بتائے ہوئے مسائل کومانناہے.مذہبی کتابوںپر خود غورکرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ان کا کا م نہیں.غرض جب قوم نبوت کے زمانہ سے دور ہوجاتی ہے اس کے حقوق بعض خاندانوں کے قبضہ میں بطورتوارث چلے جاتے ہیں اورعام لو گ دین اوردنیا کے معاملہ میں بھی مشورہ دینے یا رائے دینے کے قابل نہیں سمجھے جاتے اور اس فرق اورامتیاز کو ایک فرضی قابلیت کا نتیجہ قرار دیاجاتاہے.ایک بادشاہ کا احمق بیٹا دنیا کاسب سے بڑاسمجھد ار سمجھا جاتاہے.وہ نادان خود ایسا مغرور ہوتاہے کہ جب دنیا کے سامنے اپنا کوئی احمقانہ اعلان کرتاہے تواس میں اس قسم کے نامعقول الفاظ استعمال کرتا ہے کہ مابدولت نے لوگوں کے فائدہ کے لئے فلاں اعلیٰ تجویز سوچی ہے جس کااظہار
Page 138
اس اعلان کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے.اور کبھی وہ اس قسم کا اعلان کرتا ہے کہ اہل دنیا کی یہ خوش قسمتی ہے کہ مابدولت فلا ں بات میں اس کے شریک ہیں اورجس قدر وہ بے وقو ف ہوتا ہے اُسی قدر زیادہ تعلّی کر تاہے.یہی حال مذہبی دنیا کاہوتا ہے.علماء کے بیٹے نیم علم رکھتے ہوئے اورغوروفکر کی طاقتوں سے محروم ہو تے ہوئے صرف اس لئے مشائخ میں سے کہلاتے ہیں کہ وہ علماء کی اولاد ہیں.اوردنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بغیر دلیل کے ان کی جاہلا نہ باتوں کو تسلیم کیا جائے اورجو ان کے سامنے خدا تعالیٰ کاکلام رکھے.اُسے ان فرسودہ قصوں اوربے معنی روایتوں کا جن کی سند ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی انکا ر کرنے والا قرار دے کر کافرو مرتد قرار دے دیا جاتاہے.نبی لوگوں کو آزادی عمل اور آزادی رائے دینے کے لئے آتا ہے ایسے وقت میں صرف ایک نبی ہی کام آسکتاہے اوران امور کاعلا ج کرسکتا ہے.جب وہ ظاہر ہوتاہےتووہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے اس کی شناخت سے محروم رہ جاتے ہیں اور وہ عالم جو جاہل کے نام سے مشہور تھے اپنی بصیرت اورپاکیزہ فطرت کی مدد سے اس پر ایما ن لے آتے ہیں.تب فرشتوں اور شیطان کی لڑائی شروع ہوجاتی ہے.اوروہ جوناقابل سمجھے جاتے تھے قابلیت کے نام پر بنی نو ع انسان کو غلام بناکر رکھنے والوں کی ایک ایک تدبیر کو اس طرح کچل ڈالتے ہیں کہ جیسے چیل مردار کی بوٹیوں کو پتھروں پر مارتی ہے اوران خود ساختہ قابلوں کی قابلیت کی قلعی کھل جاتی ہے اورمدتوں سے دبے ہوئے عوام کو پھر اُبھرنے کا موقعہ ملتاہے.اورانسانیت پھر آزادی کاسا نس لیتی ہے.یہی مضمون ہے جسے اس آیت میں بیان کیاگیااوربتایاگیا ہے کہ جس کے قبضہ میں خدا تعالیٰ کی نعمت آجائے وہ انہیں جنہیں اس نے غلام بناکر رکھا ہے.کبھی اپنے حصہ میں برابر کا شریک نہیں بناتا.بھلا کبھی بھی بنی نوع انسان کو ایسے لوگوں نے آزادی رائے اورآزادی عمل دی ہے.اگر نہیں توپھر نبیوں کے سوا جووقتاً فوقتاً آکر دنیاکو آزادی بخشیں اورکون سی صورت انسا ن کی ترقی کی رہ جاتی ہے ؟ شریعت کے نزول کی ضرورت اس دلیل میں نبوت کی عملی ضرورت کوثابت کیا گیا ہے اوریہ ایسی زبردست دلیل ہے کہ ہر صاحبِ بصیر ت اسے دیکھ کر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ نبوت کے بغیر کبھی بھی دنیا اپنے حقوق کو برقرار نہیں رکھ سکتی.یہ نعمت جب تک دنیا کو بار بار نہ ملے انسان کاقدم ترقی کی طرف نہیں بڑ ھ سکتا.اَفَبِنِعْمَۃِ اللّٰہِ سے عوام الناس کو ملامت اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ سے عوام الناس کو ملامت کی ہے کہ تمہاری ہی آزادی کے لئے یہ رسول آیا ہے.اور تم اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے انہی ظالموں کے ساتھ مل کر کام کررہے ہو جو تمہار ے حقوق پر ناجائز طورپر قابض ہورہے ہیں.
Page 139
ملکیت کے بارہ میں اسلامی نقطہ نگاہ اس آیت میں نہایت لطیف پیرایہ میں اس قانون کو جو ملکیت کے بار ہ میں اسلام نے پیش کیا ہے بیان کیاگیا ہے.ایک طرف رِزْقِھِمْ کہہ کر مال و امتعہ پر ان لوگوں کا قبضہ تسلیم کیاگیا ہے جومالدار اوربڑے ہوتے ہیں.دوسری طرف بِرَادِّی کہہ کر جس کے معنے واپس لوٹانے والے کے ہیں یہ امر تسلیم کیاہے کہ مال کے مالک عوام الناس ہیں.کیونکہ لوٹائی وہی چیز جاتی ہے جودوسرے کی ہو.اپنی چیز دی جاتی ہے لوٹائی نہیں جاتی.پس ان دوالفاظ سے بظاہرمتضاد مضمون نکلتا ہے.بِرَآدِّيْ رِزْقِهِمْ سے ہر چیزپر دو ملکیتوں کی طرف اشارہ رِزْقِھِمْ بتاتا ہے کہ مالدار لو گ اپنے مالوں کے مالک ہیں اور بِرَادِّی بتاتا ہے کہ عوام الناس ان مالوں کے مالک ہیں.مگر درحقیقت اس میں تضاد نہیں.اسلام نے ملکیت پر بعض حقوق بنی نوع انسان کو دئیے ہیں اور بعض کمانے والے کو اسلام کی تعلیم کاامتیاز ی نشان ہی یہ ہے کہ اس نے ہر چیز پر دوملکیتوں کو تسلیم کیاہے.اس شخص کی ملکیت کو بھی جس نے اسے کمایا اورمن حیث الجماعت بنی نوع انسان کی ملکیت کو بھی.بعض حقو ق کمانے والے کودئے گئے ہیں.اوربعض حقوق بنی نوع انسان کو.کیونکہ اصل ملکیت دنیا کی اشیاء پر ہرانسان کو بحیثیت انسان حاصل ہے.پھر یہ کوشش بھی کی گئی ہے کہ قبضہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے انسانوں کی ترقی میں روک ہو.بلکہ و ہ دروازے کھلے رہیں جن میں سے ہوکر دوسرے لوگ بھی آگے آسکیں.اس پر زکوٰۃ،ورثہ اورسونے چاندی کے جمع کر نے کی ممانعت ،سود کی ممانعت وغیر ہ مسائل سے بہت واضح روشنی پڑتی ہے.مگر یہ موقعہ ان امو رکے بیان کا نہیں.خلاصہ یہ کہ اسلام نہ توبے قید شخصی ملکیت کا قائل ہے اورنہ غیر محدود جماعتی تصرف کا.وہ دونوں کو قیود سے پابند کرکے انفرادی اورجماعتی کشمکشوں کو اپنے اپنے دائرہ میں اپنی قابلیتوں کے اظہار کاموقعہ دیتا ہے.مَامَلَکَتْ اَیْمَانُھُمْ اس سے مراد عام طورپر غلام ہیں اورقرآن مجید کے محاورہ میں بھی اکثر جگہ یہی معنے مستعمل ہوئے ہیں.مگر اپنی بناوٹ کے لحا ظ سے یہ لفظ عام ہے.جوشخص کسی نہ کسی لحاظ سے کسی کے قبضہ و تصر ف میں ہو وہ بھی اس لفظ کے اندر شامل ہے.اس لحاظ سے تما م ماتحت نوکر ،مزارعین اورمزدوروغیرہ اس کے اند رشامل ہوں گے.اس آیت میں شریعت کے خود بنا نے والوں کا جواب اس آیت میں اس سوال کا بھی جواب دیا گیاہے کہ شریعت ہم خود ہی بنالیں گے خدائی الہام کی کیا ضرورت ہے.اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتاہے کہ شریعت بنانا خدا کا ہی حق ہونا چاہیے کیونکہ صحیح قانون وہی بناسکتا ہےجس کی اپنی غرض حقوق کی تقسیم میں کوئی نہ ہو.اگرغرض والا
Page 140
شخص شریعت بنائے گا تووہ اپنا اوراپنی قوم کا فائدہ مدنظر رکھے گا.مثلاًاگر شریعت کابنانامَردوں کے سپرد ہوگا تووہ عورتوں کے حقوق پوری طرح ادانہ کریں گے اوراگر امراء قانون بنائیں گے تووہ امراء کے حقوق کا خاص خیال رکھیں گے اورغرباء کے حقوق کو نظرانداز کردیں گے.علیٰ ہٰذاالقیاس جوکوئی بھی قانون بنائے گا وہ اپنے حقوق کازیادہ خیا ل رکھے گااوردوسروں کے حقوق پو ری طرح ادانہ کرے گا.اس لئے فرمایا کہ ہم نے شریعت بندوں کے اختیار میں نہیں رکھی تاایسانہ ہو کہ جس کے قبضہ میں کوئی نعمت آئی ہوئی ہووہ اُسے دباکے بیٹھا رہے.اوراس کا بیان کرنا اپنے ذمہ رکھا ہے تاکہ عوام الناس کو جو بطورغلاموں کے ہیں اوراپنے حقوق منوانے میں کوئی آواز نہیںرکھتے ان کو ان کے حقوق دلوائے جاتے رہیں.وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ اوراللہ(تعالیٰ)نے تمہارے لئے خود تم ہی سے بیویاں بنائی ہیں اور(نیز)اس نے تمہاری بیویوں سے تمہارے مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ١ؕ لئے بیٹے اورپوتے پیداکئے ہیں اوراُ س نے تمہیں تما م(قسم کی)پاکیزہ چیزوں سے رزق بخشا ہے کیاپھر اَفَبِالْبَاطِلِ۠ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ۰۰۷۳ (بھی)ایک ہلاک ہونے والی چیز پر (تو)وہ ایمان رکھیں گے اوراللہ(تعالیٰ )کے انعام کاوہ انکار کردیں گے حلّ لُغَات.مِنْ اَنْفُسِکُمْ:اَنْفُسُ نَفْسٌ کی جمع ہے.اورنَفْسُ الشَّیْءِ کے معنے ہیں عَیْنُہٗ.خود وہی چیز(اقرب)پس مِنْ اَنْفُسِکُمْ کے معنے ہو ں گے.کہ خود تم ہی میں سے.حَفَدَۃً.حَفَدَۃً جمع ہے اوراس کامفرد اَلْحَافِدُ ہے اوراس کے معنے ہیںاَلْخَادِمُ.نوکر.اَلنَّاصِرُ.مددگار.اَلتَّابِــعُ.تابع.وَلَدُالْوَلَدِ.پوتا(اقرب) الباطل اَلْبَاطِلُ ضِدُّالْحَقِّ.جھوٹ.(اقرب) تفسیر.توحید کامل کا تقاضا کامل رہنمائی ہے ان آیات میں بدل بدل کر شریعت کے نزول کی ضرورت اورشرک کے مضمون کو بیان کیاگیا ہے یونہی بے جوڑ طورپرنہیں.بلکہ ایک دوسرے کی تائید کے لئے.
Page 141
اوریہ ثابت کیاگیاہے کہ الہام کے بغیر انسان شرک جیسی مرض میں مبتلاہو جاتا ہے اورتوحید کامل تقاضاکرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کرے.کیونکہ جب خداایک ہی ہے توبندوں کی ہدایت کاکام کسی ودسرے پر کس طرح چھوڑ سکتا ہے.اگر کئی خداہوتے تو ایک دوسرے پر کام چھو ڑدیتا.جیسے بچوںکی نگرانی کاکام بعض دفعہ ماں، باپ پر چھو ڑ دیتی ہے اوربعض دفعہ باپ ،ماں پرچھوڑ دیتا ہے.مگرایک ہی خالق،ایک ہی مالک کس پراس کام کوچھوڑ دے.وہ توخود ہی کرے گا.اسی طرح توحید کمال کو چاہتی ہے اوربنی نوع انسان کوکسی مقصد کے بغیر پیداکرنانقص پردلالت کرتا ہے.اورتوحید کاعقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا.شریعت اور بعث بعد الموت لازم ملزوم ہیں پس اگرانسا ن بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہواتوپھر بعد الموت زندگی بھی ضروری ہے.اوراگر وہ زندگی ضروری ہے توایسی وسیع زندگی کے لئے تیار کر نے کی غرض سے ایک شریعت اورہدایت کا خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا بھی ضروری ہے.پس اسی سلسلہ میں اپنے موقعہ پر بعد الموت کی زندگی کاثبوت بھی بیان کیاگیاہے.توحید اور آسمانی ہدایت کی ضرورت کا بیان غرض توحید اورآسمانی ہدایت کی ضرورت کے مضمون کو ایک دوسرے کی تائید میں اس طرح بدل بدل کر لایا گیا ہے کہ مضمون میں ایک غیر معمولی شوکت پیداہوگئی ہے اورصاف معلوم ہوتاہے کہ جس طرح مادی دنیا کے تما م اجرام ایک دوسرے پرسہارالئے کھڑے ہیں اسی طرح روحانی دنیا کی عمارت بھی ایک دوسرے کوسہارادے رہی ہے.اوراس کاایک حصہ دوسرے کی اس طرح تائید کررہا ہے کہ جدھر سے بھی رخ کرو ایک ہی حقیقت اورایک ہی نظام کی طرف رہنمائی ہوتی ہے.توحید عین فطرت ہے چنانچہ اس آیت میں پھر توحید کی طرف رخ کیا ہے اوربتایا ہے کہ جہاں دولت و حکومت پر انسانی قبضہ ا س طرف رہنمائی کرتا ہے کہ انسانی فطرت دوسرے انسانوں کوجواس کے محکوم ہیں اپنے ساتھ شریک کرنے پر تیار نہیں ہوتی اوراس وجہ سے ایک بیرونی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے جواس بگڑے ہوئے نظام کو بدل کر مساوات انسانی اورحقوق انسانی کو قائم کرے.اسی طرح اس سے خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے اوروہ اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نعمت دیتا ہے.توجہاں تک وہ تمہارے قبضہ کو تسلیم کرتا ہے وہ تمہارے حقوق تمہاری اولاد کی طرف بطور وراثت منتقل ہونے کی اجازت دیتاہے اور تم اپنے اچھے مال جو خدا تعالیٰ نے تم کو دئے ہیں.اپنی اولاد کی طرف منتقل کرتے ہو ئے دوسروں کو نہیں دےدیتے اورنہ دوسروں کو یہ حق دیتے ہو کہ وہ تمہاری جائداد جس کوچاہیں دے دیں.پھر کیا وجہ ہے کہ تم باطل یعنی شرک میں مبتلاہوتے ہو اوراللہ تعالیٰ کی نعمتوں
Page 142
کاانکار کرتے ہو.یہ انکار وہ کس طرح کرتے ہیں اس کا ذکر اگلی آیت میں کیاگیاہے.وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ اوروہ اللہ (تعالیٰ)کوچھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمانوںاورزمین میں سے ان کے (دینے کے ) السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ شَيْـًٔا وَّ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ۚ۰۰۷۴ لئے کسی رزق کے ذرہ بھر (بھی)مالک نہیں اورنہ ہوسکتے ہیں.حل لغات.السَّمٰوٰتِ اور وَالْاَرْضَ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۴.السَّمٰوٰتُ.سَمَاءٌ کی جمع ہے.اَلسَّمَاءُ.آسمان.کُلُّ مَاعَلَاکَ فَاَظَلَّکَ.ہر اوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز.سَقْفٌ کُلِّ شَیْءٍ وَبَیْتٍ چھت رِوَاقُ الْبَیْتِ برآمدہ.ظَھْرُالْفَرَسِ گھوڑے کی پیٹھ.اَلسَّحَابُ.بادل.اَلْمَطَرُ بارش.اَلْمَطْرَۃُ الْجَیِّدَۃُ ایک دفعہ کی برسی ہوئی عمدہ بارش.اَلْعُشْبُ سبزہ و گیاہ (اقرب) اَلْاَرْضُ: کرۂ زمین.کُلُّ مَاسَفَلَ ہر نیچے کی چیز (اقرب) تفسیر.شرک اللہ تعالیٰ پر ظلم ہے فرماتا ہےکہ ان کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اس حق کو تسلیم کیا ہے کہ ان کے مال اوران کی جائدادیں ان کی اولادوں کو ملیں.مگریہ لوگ خدا تعالیٰ پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ اس کے اختیارات اوراس کی حکومت ان کو دے دیتے ہیں جن کو اس نے اپنا وارث تجویز نہیں کیا.یعنی خدا تعالیٰ تواپنے اختیارات سپرد نہیں کرتااوریہ کردیتے ہیں گویا اپنے متعلق توان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اختیارات انہیں ملیں جوہماری اولاد ہیں اورجن سے ہم تعلق رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اختیار ات خود ہی ان کے سپرد کردیں جن کو خدا تعالیٰ وہ اختیارات دینا نہیں چاہتا اور جن کو اس نے ایسے اختیارات نہیں دیئے.حالانکہ اگر باوجود اس کے کہ ان کی جائدادیں حقیقی طورپر ان کی مقبوضہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں.ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جن کو اپنا وارث سمجھتے ہیں اپنی جائدادیں ان کو دے دیں تو خدا تعالیٰ کو کیوں اختیار نہیںکہ وہ اپنی منشاء کے مطابق اپنے دین کا وارث ان کو بنائے جنہیں وہ پسند کرتاہے.شرک انسانی ترقی میں روک ہے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیاگیا ہے کہ شرک کی وجہ سے انسانی ترقی بھی رک جاتی ہے.کیونکہ جب مشرک کی توجہ ان ہستیوں کی طرف ہوجاتی ہے جن کو کوئی طاقت حاصل نہیں
Page 143
توان سے تواسے کوئی فائدہ ملتا نہیں ہاں یہ نقصان ضرو رپہنچ جاتاہے کہ اس ہستی کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے جو ان کو ہراک قسم کی نعمتیں دے سکتی ہے.اس لئے ہمیشہ مشرک قوموں کی ذہنی ترقی رک جاتی ہے اوردینی امور میں ان کا فکر نہایت کُند ہو جاتا ہے.اس کے مقابل پر جو اقوام مشرک نہیں ہوتیں اگرکسی وقت سچائی سے ہٹ بھی جائیں توان کی ذہنی ترقی کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہے.کیونکہ وہ اس وجود کے متعلق غور کرتی رہتی ہیں جس میں سب طاقتیں ہیں.پس کچھ نہ کچھ سچائی ان کو بغیر الہام کے بھی ملتی رہتی ہے.فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا پس (اے مشرکو)تم اللہ (تعالیٰ)کے متعلق (اپنے پاس سے )باتیں مت بنائو اللہ(تعالیٰ)یقیناً(سب کچھ)جانتا تَعْلَمُوْنَ۰۰۷۵ ہے اور تم (کچھ بھی)نہیں جانتے.حلّ لُغَات.لَاتَضْرِبُوْا لِلہِ الْاَمْثَالَکے معنے ہیں کہ تم اللہ کے متعلق باتیں مت بنائو.مزید تشریح کے لئے دیکھو سورۃ رعد آیت نمبر۳۶.زیر آیت النحل ۶۱جلدھٰذا.تفسیر.لَاتَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ کے معنی یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق خود قانو ن نہ بنائو کیونکہ تم تواللہ تعالیٰ کی قدرتوں تک سے ناواقف ہو.وہ جس قدر حقوق دین کے بارہ میں بندوں کو دینا پسند کرتا ہے آپ ہی اپنے بندوں کو دے گااوران کو دے گاجن کو وہ ان کے اخلاص کی وجہ سے اپنی روحانی اولاد کامرتبہ بخشتاہے.الہامی کلام میں خدا سے مراد بعض دفعہ الہامی کلام میں بعض نبیوںکو خدا تعالیٰ کے بیٹے کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے جیسا کہ مسیح علیہ السلام کے بارہ میں آتاہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے.چنانچہ انجیل میں آتا ہے کہ مسیح نے حواریوں سے کہا کہ:.’’پس تم جاکر سب قوموں کو شاگرد بنائو اورانہیں باپ اوربیٹے اورروح القد س کے نام سے بپتسمہ دو.‘‘ (متی باب ۲۸آیت۱۹) اس جگہ بیٹے کے لفظ سے اسی طرف اشارہ کیاگیاہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کرکے اپنی آسمانی بادشاہت کاوارث بنایا تھا.قرآن کریم میں بھی اس مضمون کا ان الفاظ میں اشارہ کیا گیاہے وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا
Page 144
سُبْحٰنَهٗ١ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ (الانبیاء :۲۷)یعنی مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیٹے پیداکئے ہیں یہ غلط کہتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ بیٹاکہتا ہے وہ صرف اس کے مکرم بندے ہیں اوراللہ تعالیٰ کامنشاء اس لفظ کے استعمال سے ان کے اعزازکوظاہر کرنا ہوتا ہے جو انہیں اس کے حضورحاصل ہے.مگرافسوس کہ نادان ان محاورات سے دھوکاکھاکر خدا تعالیٰ کے عاجز بندوں کو حقیقتاًخدا تعالیٰ کابیٹاسمجھنے لگتے ہیں اوربعض دوسرے نادان ان محاورا ت پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں.آیت اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ الخ سے الہامی کلام میں ہر لفظ کی حقیقت پر مبنی ہونے کی طرف اشارہ اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ میں اس طرف اشارہ کیا گیاہے کہ خدا تعالیٰ جو لفظ استعمال کرتاہے وہ ایک ایسی حقیقت پر مبنی ہوتاہے جواس کی دوسری صفات کے مخالف نہیں ہوتی.مگرتم ایسے معنوں میں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہو جومحض جہالت کااظہارکرتے ہیں.ان سے کوئی حقیقت بھی توظاہر نہیں ہوتی.مثلاًخدا تعالیٰ جن معنوں میں بیٹاکہتا ہے اس سے تو اس گہرے تعلق کااظہار مقصودہوتاہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے پاک بندوں سے ہے.مگرمشرک اسے حقیقی بیٹا بنا کر کے اس پاکیز ہ تعلق کو ایک جسمانی تعلق بنادیتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کی عظمت کو بھی گرادیتے ہیں اوران بندوں کی بھی ہتک کرتے ہیں جن کو وہ معبود بناتے ہیں.کیونکہ اس طرح وہ ان کے متعلق اس عظمت کا تو انکار کر دیتے ہیں جو عرفان اورقربانی سے حاصل ہوتی ہے.اوروہ فرضی عظمت ان کو دیتے ہیں جو جسمانی تعلق سے حاصل ہوتی ہے اورجو پہلی کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی.ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّ اللہ(تعالیٰ تمہارے سمجھانے کو )ایک ایسے بندے کی حالت بیان کرتا ہے جو غلا م ہو (اور)جوکسی بات کی(بھی) مَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّ طاقت نہ رکھتا ہو اور(اس کے مقابلہ میں اس بندے کی حالت کوبھی )جسے ہم نے اپنےپاس سے اچھا رزق دیاہو جَهْرًا١ؕ هَلْ يَسْتَوٗنَ١ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ١ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا اوروہ اس میں سے پوشیدہ طورپر (بھی )اورعلانیہ طورپر (بھی ہماری راہ میں )خرچ کرتاہو.کیاو ہ دونوں (قسم کے
Page 145
يَعْلَمُوْنَ۰۰۷۶ لوگ)برابر ہوسکتے ہیں (ہرگز نہیں )تمام تعریف (تو)اللہ (تعالیٰ)ہی کو (سزاوار)ہے.لیکن ان میں سے اکثر(لوگ)جانتے نہیں.تفسیر.روحانی امور میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد پر کھڑا رہنا چاہیے چونکہ پہلی آیت میں اس طرف اشار ہ تھا کہ روحانی امور میں ا س حد پر کھڑا رہناچاہیے جواللہ تعالیٰ مقرر کر ے.ورنہ انسان دھوکاکھا کر کہیں کاکہیں چلاجاتاہے اوراس طرف اشارہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بعض بندوں کوعزت دے کر بعض پیار کے ناموں سے یادکرتاہے تواس کے اَورمعنے ہوتے ہیں اورمشرک جب ویسے ہی ناموں سے مخلوق میں سے بعض کو یاد کرتے ہیں تواس کے معنے اورہوتے ہیں.آزاد اور غلام کی مثال میں آنحضرت ؐ کے لئے اچھے الفاظ کا استعمال اوراس کی مثال کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اشارۃً پیش کیا اورفرمایاکہ کیا تم سوچتے نہیں کہ ایسا شخص جو ہو اوہوس کا شکار ہو اور عبد مملوک کی حیثیت رکھتاہو اوربوجہ دوسروں کاغلام ہونے کے اپنی قابلیتوں کاصحیح استعمال نہ کرسکتا ہو اوررسم و رواج اورتوہمات کی قیود میں جکڑاہواہو اوراسے ایک غلا م کی حیثیت حاصل ہو کیا ا س دوسرے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جورسوم اورتوہمات کی غلامی سے آزاد ہو کر خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے ظاہر اورمخفی طور پر خدا تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرتا رہتا ہے.یقیناًاللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرے گا جو اس کی دی ہوئی قوتوںکو مفید طورپر اس کے بندوں کی خد مت میں لگاتا ہے اوریہی شخص کامیاب ہوگا.اس مثال سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی طرف اشارہ کیا گیاہے اوربتایا ہے کہ یہ شخص ہی خداکے فضلوں کاوارث ہو سکتا ہے اوراس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ جو بھی اچھے الفاظ استعمال فرمائے وہ ان کامستحق ہے.محمد رسول اللہ کی کامیابی کی وجہ اس میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تم تو خدا تعالیٰ کے دئے ہوئے انعامات سے صرف اپنے خاندانوںاوراولاد کو فائدہ پہنچاتے ہو اورمحمدؐ رسول اللہ سب دنیا کو اپنے انعامات میں شریک کرتاہے.پس اس کی کامیابی یقینی ہے اور تمہاری ناکامی یقینی.سِرًّاوَّجَھْرًا کے تین معنی سِرًّاوَّجَھْرًاکے تین معنے ہوسکتے ہیں :.۱.پوشیدہ طورپر بھی ظاہر بھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی وہ خدمت بھی کرتے تھے
Page 146
جولوگوں کو نظر نہ آتی تھی جیسے دعااوراستغفار.اوروہ بھی جو لوگوں کو نظر آتی تھی.جیسے وہ اخلاق فاضلہ جو بنی نوع انسان کے متعلق آپ سے ظاہر ہوتے تھے جن کا ذکر حضرت خدیجہؓ کے اس قول میں ہے کہ کَلَّاوَاللہِ مَایُخزِیْکَ اللہُ اَبَدًااِنَّکَ لَتَصِلُ الرِّحْمَ وَتَحْمِلُ الْکَلَّ وَتَکْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِی الضَّیْفَ وَتُعِیْنُ عَلٰی نَوَائِبِ الْحَقِّ (بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی) یعنی خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگزنہ چھوڑے گا.کیونکہ آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے اورمہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اوران اخلاق کوظاہر کرتے ہیں جو دنیا سے مفقود ہوچکے تھے اورجو لوگ ایسے مصائب میں مبتلاہو ںجوناحق ان پر پڑ گئے ہوں ان کی آ پ مدد کرتے ہیں اورجوشخص بالکل بے بس ہوتاہے ا س کابوجھ آپ اٹھالیتے ہیں.سِرًّاوَّجَھْرًا کے معنی رات اور دن کے ۲.دوسرے معنے اس کے رات او ردن کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ رات کاکام مخفی ہوتاہے اوردن کا ظاہر.اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ نے خدمت خلق میں رات اور دن ایک کردئے ہیں اوربغیر آرام کرنے کے بنی نوع انسان کی بہتری میں کوشاں رہتے ہیں.آنحضرت ؐ کا سِرًّاوَّجَھْرًا بنی نوع انسان کی خدمت کرنا ۳.تیسرے معنے یہ ہیں کہ آپؐ وہ خدمات بھی کرتے ہیں جولوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں.یعنی ان کی قدر نہیں جانتے جیسے تبلیغ حق.کہ لو گ اپنی جہالت کی وجہ سے اُسے خدمت نہیں سمجھتے تھے حالانکہ وہ اعلیٰ درجہ کی خدمت تھی اورآپ وہ خدمات بھی کرتے ہیں جن کو لوگ پہچانتے ہیں اوران کی خوبی کااعتراف کرتے ہیں.مثلاً ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی حضورکے پاس آیا اورعرض کیا کہ ابوجہل میراروپیہ نہیں دیتا.آپ اُسی وقت اس آدمی کے ساتھ چل کھڑے ہوئے.اورابوجہل کے دروازہ پر دستک دی.ابوجہل باہر نکلا اورحضورکو کھڑے دیکھ کر حیران سارہ گیا اورآنے کی وجہ دریافت کی.(کیونکہ وہ تودن رات آنحضرت صلعم کی ایذادہی اورسبّ وشتم میں مشغول رہتاتھا.اس کے لئے آپ کا اس کے پا س آنا تعجب کاموجب تھا )آپؐ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس شخص کاروپیہ دینا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں دینا ہے.آپؐ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو اس شخص کو پریشا ن نہ کروفوراً اس کاحق اداکرو.وہ ایسا مرعوب ہواکہ گھر جاکر فوراً روپیہ لے آیا اوراس شخص کو دے دیا.جب لوگوں میں اس بات کا چرچا ہواتولوگوں نے ابوجہل کوملامت کی کہ آپ ہم سے تویہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بات نہ مانو اورخود اس سے ایسے ڈر گئے.اس نے جوا ب دیا کہ کیا بتائوں اس وقت مجھے یہ معلوم ہوتاتھا کہ میں نے اس کی بات کاانکار کیا تو ایک وحشی اونٹ اسی وقت مجھ کوچباجائے گا اورمیں نے اس ڈر سے اس کی بات کو مان لیا.(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام ،ابوجھل أمر الأراشی....)
Page 147
ممکن ہے کہ کشفی طورپر واقعی ایک مست اونٹ بھی آپ کے ساتھ اسے نظرآگیا ہو.مگرآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں فرمایا.اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابوجہل نے بعد میں اپنے ڈرکوچھپانے کے لئے جو آ پ کے سچ کی تائید کرنے کی وجہ سے ہوااورکفار کے اعتراض سے بچنے کے لئے بہانہ بنا کر یہ بات کہہ دی ہو.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کے بعض نیک اعمال مخفی ہوتے ہیںاوربنی نوع انسان ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے.اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا یوم جزاء لائے جس میں اس کے ایسے اعمال بھی دنیا پرظاہر کئے جائیں اور اُسے اپناحق مل جائے.وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ اوراللہ (تعالیٰ)دواورشخصوں کی حالت (بھی )بیان کرتا ہے جن میں سے ایک گونگا ہو جوکسی بات کی طاقت نہ رکھتا عَلٰى شَيْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ١ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ ہو اوروہ اپنے مالک پر بے فائدہ بوجھ ہو جدھر بھی (اس کا آقا)اسے بھیجے (وہ)کوئی بھلائی (کما کر )نہ لائے بِخَيْرٍ١ؕ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ١ۙ وَ مَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ١ۙ وَ هُوَ (پس)کیا وہ (شخص) اور وہ (دوسرا)شخص جو انصاف کرنے کاحکم دیتاہو اوروہ (خود بھی )سیدھی راہ پر (قائم) عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍؒ۰۰۷۷ ہو باہم برابر ہوسکتے ہیں.حلّ لُغَات.اَبْکَمُبَکَمَ یَبْکَمُ بَکْمًاکے معنے ہیں خَرِسَ.گونگاہوگیا.فَھُوَ اَبْکَمُ.اور اس سے صیغہ صفت اَبْکَمُ آتاہے.(اقرب) اَلْکَلُّ اَلْمُصِیْبَۃُ.اَلْکَلُّ کے معنے مصیبت.اَلثَّقِیْلُ لَاخَیْرَ فِیْہِ.ایسا بوجھ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو.اَلْعَیِّلُ الْعِیَالُ.گھر کے لوگ جن پر خرچ کرنا پڑتا ہے.اَلثِّقَلُ.بوجھ.اَلضَّعِیْفُ.کمزور.وَیُطْلَقُ الْکَلُّ عَلی الْوَاحِدِ وَغَیْرِہِ اور کَلُّ کا لفظ واحد تثنیہ جمع سب کے لئے استعمال کرتے ہیں.(اقرب)
Page 148
المولیٰ.اَلْمَوْلٰی کے معنے کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۳۱.اَلْمَوْلٰی اَلْمَالِکُ.مالک.اَلْمُعْتِقُ آزاد کرنے والا.اَلصَّاحِبُ.ساتھی.آقا اَلْحَلِیْفُ.معاہد.اَلرَّبُّ.رب.اَلْوَلِیُّ کارساز.اَلْمُنْعِمُ.محسن.اَلْمُحِبُّ محبت کرنے والا.اَلْقَرِیْبُ.رشتہ دار.(اقرب) یُوَجِّھْہُ وَجَّھَہٗ اِلَیْہِ فِیْ حَاجَۃٍ کے معنے ہیں.اَرْسَلَہٗ فَوَجَّہُ اِلَیْہِ اَیْ فَذَھَبَ لَازِمٌ وَمُتْعَدٍٍّّ.اس کوکسی ضرورت کے لئے بھیجا اوروہ اس کے لئے چلا گیا.یہ لفظ لازم اورمتعدی دونوں طرح استعما ل ہوتا ہے (اقرب) پس اَیْنَـمَا یُوَجِّھْہُّ کے معنے ہوں گے جہاں کہیں وہ اسے بھیجتاہے.صراط.اَلصِّرَاطُ اَلطَّرِیْقُ.راستہ (اقرب) تفسیر.اس آیت میں پہلے مضمون کی مزید وضاحت اس آیت میں پہلے مضمون کو ایک اَورمثال سے واضح کیا.پہلی مثال میں تویہ بتایا تھا کہ اگر ایک شخص گوقابلیت تورکھتاہو لیکن بوجہ دوسروں کے قبضہ میں ہونے کے اس میں اس قابلیت کے اظہار کی طاقت نہ ہو تواس کا وجو د اورعد م وجود برابر ہوتاہے.اب اس آیت میں ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرمائی ہے جوگونگا ہو اور کسی نیک کام کے کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتاہو ایساشخص بھی کسی فضل کا مستحق نہیں ہوتا.کیونکہ نہ تو اس میں کام کی طاقت ہوتی ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے اور نہ اس کی زبان چلتی ہے کہ منہ سے ہی لوگوں کو نیک باتوںکی تعلیم دیتارہے.پھر فرمایا کہ ان عیوب کی وجہ سے اس کا آقا جوکا م بھی اس کے سپرد کرے وہ اسے پورانہیں کرسکتا.لیکن اس کے مقابل پر وہ غلام جو اپنے مالک کے حکم کے مطابق لوگوں کو بھی عدل کرنے کاحکم دیتاہو اورخود بھی سیدھے راستے پرقائم ہو یعنی نیک کام کرکے اپنے آقا کو خوش کرتارہتاہو.بڑی فضیلت رکھتاہے اوریہ دونوں کسی صورت میں برابر نہیں ہوسکتے.اورآقاان دونوں سے یکساں سلوک نہیں کرسکتا.آنحضرت ؐ اور کفار کے ایک گروہ کا مقابلہ اس آیت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اورکفار کے ایک گروہ کامقابلہ کرکے دکھایاہے.فرماتا ہے.تم گونگے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے تما م عیب کئے جاتے تھے.شرک ہوتاتھا اورہورہا ہے خدا کی صفات کو غلط طور پر پیش کیا جاتاتھااور کیا جاتا ہے.مگر تم میں سے کسی کی زبان نہ ہلی.اور کسی نے لوگوں سے نہ کہا کہ شرک نہ کرو اورخدا کی ہتک نہ کرو.اگر کسی نے زبان ہلائی اورحق بیان کیا اوراپنے آقا کی عزت کے تحفظ کے لئے کلمہ خیر کہا تووہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.پھر اسی پر بس نہیں اگرتم دوسروں کو نیکی کاحکم نہ دے سکتے تھے توخود ہی نیکی پر قائم رہتے اوراپنے نیک اعمال سے خدا تعالیٰ کی سبوحیت اورپاکیز گی کااعلان کر تے.شرک سے دوسروں کو نہیں روک سکتے تھے توکم از کم خود توشرک
Page 149
نہ کرتے مگر تم سے یہ بھی نہ ہوا.پھر دین کو جانے دو.تم اگردنیا کے اموال اورمتاع کے پیچھے پڑے تھے تواسی میں ترقی کی ہوتی.مگر تم تو دنیا میں بھی دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے خود بوجھ بن رہے ہو.مگر اس کے مقابل پر محمد(صلی اللہ علیہ وسلم )کو دیکھو کہ وہ غیروں کو انصاف کاحکم دیتے ہیں اوراپنی ذات میں صراط مستقیم پر ہیں.یعنی ہرلحاظ سے کامل ہیں.اب تم ہی بتائو کہ ہم اس کی مد دکریں یا تمہاری ؟ آیت ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا میں دو قسم کے کفار کی حالت کا بیان اس آیت او راس سے پہلی آیت میں دو قسم کے کفار کی حالت کو بیان کیاہے اوران دونوں گروہوں کے مقابل پر رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو پیش کیا ہے.ایک قسم کفار کی یہ بیان کی کہ وہ رسوم و توہمات کے غلام ہیں اورگوان میں کام کی قابلیت توہے مگر وہ لوگوں کے ڈر سے کام کر نہیںسکتے.اوردوسری قسم کے کفار کی حالت یہ بتائی کہ وہ رسوم و توہمات کے غلام بھی ہیں اوران کی قابلیتیں بھی ماری گئی ہیں.اگر رسوم اورتوہمات سے آزاد بھی ہوجائیں تب بھی ان کی حالت ایسی مسخ ہوچکی ہے کہ وہ کوئی نیک کام نہیں کرسکتے بلکہ اللہ تعالیٰ پر بوجھ ہیں کہ اس کی سبوحیت پر ان کے وجود سے داغ لگ رہا ہے.اس کے مقابل پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے غلام نہیں اورجو طاقتیں انہیں ملی ہیں انہیں بنی نو ع انسان کی خدمت میں لگارہے ہیں.نیز وہ زبردست روحانی طاقتیں رکھتے ہیں جن کی مدد سے خود بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق دکھاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اب تم خود ہی سوچو کہ ایسے شخص کو ہم اپنے کام کے لئے چنیں گے جو قابل بھی ہواورہمارے دین کی خدمت بھی کررہا ہو یااس گروہ کو جوقابل توہو مگر اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں لگانے سے معذورہو.کیونکہ وہ رسم و رواج کی طاقت کا مقابلہ نہیں کرسکتا.یاپھر ا س کو جو نہ توقا بل ہو نہ رسم و رواج کی قیود سے آزاد.وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ وَ مَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا اورآسمانوں اورزمین کی ہرپوشیدہ چیز(بھی)اللہ( تعالیٰ)ہی کی ہے.اوراس (موعودہ)گھڑی(کی آمد)کامعاملہ تو كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کاجھپکنا بلکہ وہ (اس سے بھی )قریب تر (وقت میں واقع ہوجانے والا)ہے.
Page 150
قَدِيْرٌ۰۰۷۸ اللہ(تعالیٰ)یقیناًہربات پر پورا(پورا)قادر ہے.حلّ لُغَات.الساعۃ اَلسَّاعَۃُکے لئے دیکھو سورۃ ہذاآیت نمبر ۶۲ جلد ھٰذا.لَمْحِ الْبَصَرِ: لَمَحَ(یَلْمَحُ لَمْحًا)الْبَصَرُ:اِمْتَدَّ اِلٰی الشَّیْءِ.کسی چیز کو آنکھ نے دیکھا لَمَحَ الرَّجُلُ الشَّیْءَ وَاِلَی الشَّیْءِ:اَبْصَرَہُ بِنَظْرٍ خَفِیْفٍ اَوِاخْتَلَسَ النَّظْرَکسی چیز پر سرسری نگاہ ڈالی.لَمَحَ الشَّیْءِ بِالْبَصَرِ :صَوَّبَہُ اِلَیْہِ.اسے ٹکٹکی لگاکر دیکھا (اقرب)پس لَمْحِ الْبَصَرِ کے معنے ہوں گے آنکھ کا دیکھنا یااتنی دیر دیکھنا جتنی دیر کہ آنکھ ایک دفعہ کھل کر پھر بند ہوتی ہے.شَیْءٍ: شَیْءٌ شَاءَ کامصدر ہے اورشَاءَ ہٗ (یَشَاءُ ہُ شَیْئًا)کے معنے ہیں.اَرَادَہُ کسی چیز کااراد ہ کیا.اللہُ الشَّیْءَ.قَدَّرَہُ.کسی چیز کااندازہ کیا نیز الشَّیْءُ کے معنے ہیں مَایَصِحُّ اَنْ یُعْلَمَ وَیُخْبَرَ عَنْہُ وَھُوَ مُذَکَّرٌ یُطْلَقُ عَلَی الْمُذَکَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَیَقَعُ عَلَی الْوَاجِبِ وَالْمُمْکَنِ جس کومعلو م کر کے اس کے متعلق خبردینی صحیح ہو اوریہ لفظ مذکر ہے لیکن مذکر اورمؤنث دونو کے لئے بولاجاتا ہے اوراللہ تعالیٰ اوردیگر مخلوقات کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.اس کی جمع اَشْیَاءٌ ہے.(اقرب) تفسیر.آنحضرت ؐ کے منکرین کی تباہی کی خبر سے ایک اعتراض کا جواب گذشتہ آیات میں بیان فرمایاتھا کہ کیاگونگے ،نکمے اورنااہل وجود ان کے برابر ہوسکتے ہیں جو عدل کی تعلیم دوسروں کودیتے اورخود نیک عمل کرتے ہیں یعنی نہیں ہوسکتے.اب بیان فرماتا ہے کہ جب یہ برے نیکوںجیسے سلوک کے مستحق نہیں ہوسکتے توسنو ہم جو زمین و آسمان کا راز جاننے والے ہیں تم کو ایک راز کی خبر بتاتے ہیں.اوروہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ہلاکت کا وقت آنکھ جھپکتے آنے والا ہے بلکہ وہ اس سے بھی قریب تر ہے.اس جگہ چونکہ یہ سوال ہوسکتا تھاکہ غیب جاننے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق نتیجہ نکالنے پر قادربھی ہو اس لئے اس آیت کو اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌکے الفاظ پر ختم کیا اوربتایا کہ ہم غیب ہی نہیں جانتے بلکہ آئند ہ ہونے والے واقعات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی بھی پور ی طاقت رکھتے ہیں.آنحضرت ؐ کے دشمنوں کی تباہی کو اتفاقی حادثہ کہنے والوں کا جواب اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تباہ ہوں گے توبعد میںآنے والے لوگ اس واقعہ کی قدر کم کرنے
Page 151
کے لئے کہیں گے کہ آپؐ کے دشمنوں کی تباہی ایک اتفاقی حادثہ تھا یایہ کہ ان کے حالات ہی ایسے تھے کہ ہلاک ہوجاتے.چنانچہ آج کل کے مسیحی مصنف اس مضمون پر بہت ہی زور دیاکرتے ہیں اورآپؐ کے مخالفوں کی ہلاکت کوطبعی امورکانتیجہ قراردیا کرتے ہیں.دیکھو قرآن کریم کا اتارنے والا عالم الغیب اس آیت میں کس طرح ان لوگوں کے اعتراض کا جواب دیتا ہے.آیت کو شروع غیب کاعلم رکھنے کے دعویٰ سے کرتا ہے اورپھر کفارکی ہلاکت کی خبر دیتا ہے اورختم ا س پر کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاقی نہ ہو گا بلکہ ہماری قدرت کے ذریعہ سے ہوگا.کس طرح اس آیت میں ایک طرف تومکہ میں رہتے ہوئے جبکہ کفار کے ظلم زوروں پر تھے اور مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہ تھی وہ ہجرت پر مجبور ہورہے تھے فرماتا ہے کہ ہم غیب کا علم رکھنے والے خداتم کو بتادیتے ہیں کہ کفار کی ہلاکت کا وقت اب آن پہنچا.اوریہ بھی بتادیتے ہیں کہ ان کی تباہی ہماری قدر ت کے ذریعہ سے ہوگی اوران حالات کے ذریعہ سے جوانسانی طاقت میں نہیں.آنحضرت ؐ کی ترقی معجزانہ ہے اب دیکھو کس طرح اس آیت کے نزول کے بعد مدینہ کے سب لو گ مسلمان ہوگئے.حالانکہ پہلے صرف چند آدمی مسلمان ہو ئے تھے اورکس طرح خود کفارنے محمد رسول اللہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبورکیا ورنہ آپؐ مکہ کو چھوڑنے پرآمادہ نہ تھے.صرف اُسی وقت آپ نے مکہ چھوڑاجبکہ کفار نے آپ کو قتل کردینے کافیصلہ کرلیا اورپھر اسی رات آپ ؐوہاں سے نکلے بلکہ اس وقت نکلے جبکہ کفار نے آپ کے گھر کامحاصرہ کرلیا.گویا کفار پر آخری حجت پوری کردی کہ میں مکہ کو چھوڑنانہیں چاہتا.مگرچونکہ تم نے میرے لئے اورکوئی راستہ نہیں چھوڑا اس لئے یہاں سے جاتاہوں.اس کے بعد کفارنے کس قدر زورآپؐ کو مدینہ میں کمزور کرنے کے لئے لگایا.مگر کس طرح آناًفاناً آپ کازوربڑھتا چلا گیا اورآخر کفار تباہ ہوئے.اسے کون اتفاقی امر کہہ سکتاہے ؟کون طبعی نتائج کہہ سکتا ہے ؟ خصوصاً جبکہ قبل از وقت پیشگوئی بھی کردی گئی تھی.مسیحی مصنف یہ تو ثابت کرسکتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے کسریٰ اورقیصر پر حملہ کیا ان کی حکومتیں تنزل کی طرف جارہی تھیں.مگرسوال یہ نہیں کہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نے جب ایران اورروم پر حملہ کیاتھااس وقت ایرانی اوررومی حکومت کی مسلمانوںکے مقابل پر کیا حیثیت تھی.بلکہ سوال یہ ہے کہ جب محمد رسو ل اللہ صلعم نے مکہ میں بیٹھے اپنی فتح اورمنکرین کی شکست کی خبر دی تھی اس وقت کو ن سی طاقت آپ کے پاس تھی ؟ اگر خدا نے آپ کو وہ طاقت دی جس نے ایک طرف عرب کو تہ و بالاکردیا اوردوسری طرف ایران و روم کو تواس کانام معجزہ نہیں تواَورکس چیز کانام معجزہ ہواکرتاہے.آنکھ جھپکنے کے معنی زمانہ قریب کے یہ پیشگوئی مکی زندگی کے آخر میں کی گئی تھی اورسب سے پہلی فتح بدرکے
Page 152
موقعہ پرہوئی گویاکوئی اڑھائی تین سال بعد.اورفتح مکہ کا واقعہ اس پیشگوئی کے بعد کوئی نودس سال بعد ہوا.لیکن اس آیت میں فتح کے وقت کی خبر ان الفاظ میں دی گئی ہے کہ آنکھ جھپکتے بلکہ اس سے بھی پہلے یہ واقعہ ہوگا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اس قسم کے الفاظ کے معنے قریب زمانہ کے ہوتے ہیں.ضروری نہیں کہ پلک جھپکنے سے پلک جھپکنا ہی مراد ہو.بعض لوگ ایسے الفاظ پیشگوئیوں میں دیکھ کر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں اورالہامی زبان کے محاورات کونظرانداز کردیتے ہیں.وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا١ۙ اوراللہ (تعالیٰ)نے تمہیں تمہاری مائوں کے پیٹوں سے اس حالت میں پیدا کیاہے کہ تم کچھ (بھی)نہیں جانتے تھے وَّ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْـِٕدَةَ١ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۰۰۷۹ اوراس نے تمہارے لئے کان اورآنکھیں اوردل پیداکئے ہیں تاکہ تم شکر اداکرو.تفسیر.فرماتا ہے کہ اے لوگوہم نے تم کو تمہاری مائوں کے پیٹ سے جبکہ تم کچھ نہ جانتے تھے تم کو آنکھ کان اوردل دے کردنیا میں بھیجا تاکہ تم علم سیکھو لیکن تم نے ہماری ا س بخشش سے کچھ بھی فائدہ نہ اُٹھایا.نہ آنکھوں سے دیکھا.نہ کانوں سے سنا.نہ دل سے سوچا.اس فقرہ میں کیسارحم اورافسوس بھراہواہے.خدائے قادراپنے بندوں کی ا س غفلت پر جس نے انہیں عذاب کامستحق بنادیا کیسے محبت سے بھرے ہوئے الفاظ میں افسوس کا اظہار کرتا ہے.وَ اللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ کا تعلق سورت کے مضمون سے اس آیت کاتعلق سورۃ کے مضمون سے یہ ہے کہ اس میں الہام الٰہی کی ضرورت کی ایک اوردلیل دی گئی ہے.اوروہ اس طرح کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے توہرایک علم سے خالی ہوتاہے.مگراللہ تعالیٰ اسے آنکھ کان اوردل دے کر پیداکرتا ہے تاوہ علم حاصل کرے اوران کی مدد سے وہ علم سیکھتا ہے.پس جو دنیو ی علوم انسان سیکھتاہے وہ سبھی اللہ تعالیٰ کے مہیا کئے ہوئے ذرائع سے سیکھتاہے.کوئی انسان ایسانہیں جوکہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے ان ذرائع کی ضرورت نہیں.میںخود ہی اپنے لئے حصول علم کے سامان پیداکروں گا.پھرروحانی علم کے سیکھنے کے لئے جوذرائع اللہ تعالیٰ پیداکرتاہے ان کے استعمال سے اُسے کیوں انکار ہوتا ہے.تعجب ہے کہ انسان کی سب عظمت ان ذرائع کے استعمال سے ہوتی ہے جواُسے قدرت عطافرماتی ہے.
Page 153
انسان کے جس قدر کمالات ہیں وہ انہی طاقتوں کی مدد سے حاصل کئے جاتے ہیں اوران طاقتو ں کے استعمال میں وہ کوئی سبکی محسوس نہیں کرتا.مگر جب روحانی ذرائع کا سوال پیدا ہوتاہے تووہ کہتاہے مجھے ان کی کیاضرورت ہے میں خود اپنا کام کرسکتاہوں.حالانکہ جس طرح اُسے مادی ترقی کے لئے عطاکردہ جوارح کی ضرورت ہے ا سی طرح روحانی کمالات کے حصول کے لئے اُسے ان سامانوں کی ضرورت ہے جواللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے اس کے لئے پیداکرتاہے.آیت کے اخیر میں فرماتا ہے کہ ان چیزوںکے دینے کی غرض تویہ تھی کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی قدرپیداہو.تم اُلٹا ان طاقتوں سے مغرور ہوجاتے ہو اورکہتے ہوکہ ہمیں کسی بیرونی مددکی ضرورت نہیں.بچہ کے اعضاء کے کام کرنے کے متعلق سائنس کی قرآن مجید کے بیان کے مطابق تحقیقات اس آیت میں کانوں کے بعد آنکھوںاورآنکھوں کے بعد دلوں کا ذکر کیا گیا ہے اوراسی ترتیب سے یہ اعضاء انسان کے علم کے بڑھانے کاموجب ہوتے ہیں.سب سے پہلے بچہ کے کان کام کرتے ہیں.ان کے بعد آنکھیں اورسب کے بعد دل یعنی قوت فکریہ کام کرتی ہے.آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے بچہ کے کان کام کرنے لگتے ہیں اوراس کے بعد آنکھیں کام شروع کرتی ہیں اورسب سے آخر میں قوت فکریہ کام کرنا شروع کرتی ہے.چنانچہ جانوروں میں بچوں کی آنکھیں بعض دفعہ کئی کئی دن کے بعد کھلتی ہیں.اس عرصہ میں صرف کان کام کررہے ہوتے ہیں.انسانوں کے بچوں کی آنکھیں بظاہر کھلی ہوتی ہیں.لیکن ان کا فعل کانوںکے فعل کے بعد شروع ہوتاہے اورقوت فکریہ تو ایک عرصہ کے بعد کام شروع کرتی ہے.یہ ترتیب بھی قرآن کریم کے کلام الٰہی ہونے کا ایک ثبوت ہے کیونکہ اس میں وہ مضمون بیان کئے گئے ہیں جواس زمانہ میں مخفی تھے.اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ١ؕ مَا کیاانہوں نے پرندوں کو جوآسمان کی فضاکے اندر مسخر کئے گئے ہیں (غورکی نظر سے)نہیں دیکھاانہیں (تم پر يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ آگرنے اورنوچ کھانے سے )اللہ(تعالیٰ)کے سوا(اور)کوئی نہیں روک رہا.جولوگ ایما ن رکھتے ہیں ان
Page 154
يُّؤْمِنُوْنَ۰۰۸۰ کےلئے اس میں یقیناًکئی نشان(پائے جاتے)ہیں.حلّ لُغَات.جَوٌّ:جَوٌّ:مَابَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ زمین اورآسمان کی درمیانی فضا.جَوُّالْبَیْتِ: دَاخِلُہٗ : گھرکااندرکاحصہ.(اقرب) یُمْسِکُھُنَّ: یُمْسِکُ اَمْسَکَ سے مضارع کاصیغہ ہے اوراَمْسَکَ الشَّیْءَ بِیَدِہٖ کے معنے ہیں.قَبَضَہٗ : کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑا.اَمْسَکَ اللہُ الْغَیْثَ: حَبَسَہٗ وَمَنَعَ نُزُوْلَہٗ اللہ تعالیٰ نے بارش کوروک دیا.اَمْسَکَ عَنِ الْکَلَامِ:سَکَتَ کلام کرنے سے خاموش رہا.اَمْسَکَ عَنِ الْاَمْرِ :کَفَّ عَنْہُ وَامْتَنَعَ:کسی کام سے رُکار ہا.(اقرب)پس مایُمْسِکُھُنَّ کے معنی ہوں گے انہیں کوئی نہیں روکتا.اَلْقَوْمُ:اَلْقَوْمُ اَلْجَمَاعَۃُ مِنَ الرِّجَالِ خَاصَّۃً وَقِیْلَ تَدْخُلُہُ النِّسَاءُ عَلٰی تَبِیْعَۃٍ سُمُّوْا بِذَالِکَ لِقِیَامِھِمْ بِالْعَظَائِمِ وَالْمُھِمَّاتِ قوم کا لفظ مردوں کی جماعت پر بولاجاتاہے اوربعض کہتے ہیں کہ اس میں عورتیں بھی بالواسطہ شامل ہوجاتی ہیں.اورمردوں پر قوم کالفظ اس لئے بولتے ہیں کہ وہ اہم امور کو سرانجام دیتے ہیں.یُذَکَّرُ وَیُؤَنَّثُ فَیُقَالُ قَامَ الْقَوْمُ وَقَامَتِ الْقَوْمُ.یہ لفظ مذکر اورمؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے.چنانچہ قَامَ الْقَوْمُ (مذکر)اورقَامَتِ الْقَوْمُ (مؤنث ) دونوں طرح کہہ دیتے ہیں.(اقرب) تفسیر.مفسرین کے نزدیک مسخرات فی جو السماء کے معنی مفسرین نے مُسَخَّرٰتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَآءِ کے یہ معنے کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ظاہری سامانوں کے ان کو جوّ میں اڑنے کی طاقت دی (تفسیر بیضاوی زیر آیت ھٰذا) اوریہ گویا اس کی قدرت کااظہار ہے.مگریہ معنے صحیح نہیں.اس آیت میں درحقیقت کفارکی سزاکا ذکر ہے.اوراللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پرندوں کوخدا تعالیٰ نے روکاہواہے مگرایک دن آئے گاکہ یہ پرندے تم پر گریں گے اور تمہاری لاشوں کو نوچ نوچ کرکھائیں گے جیساکہ بعد کی جنگوں میں ہواکہ کئی جنگوںمیں کفار میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے راستوں پرلاشیں چھوڑ گئے اورو ہ پرندوں کی خوراک بنیں.نابغہ ذبیانی کا ایک شعران معنوں کی تائید کرتا ہے وہ کہتاہے اِذَامَاغَدٰی بِالْجَیْشِ حَلَّقَ فَوْقَہٗ عَصَائِبُ طَیْرٍ تَھتَدِیْ بِالْعَصَائِبِ
Page 155
یعنی میراممدوح ایساہے کہ جب و ہ لشکر لے کر نکلتا ہے توپرندے اس کے ساتھ اڑتے جاتے ہیں کیونکہ و ہ جانتے ہیں کہ یہ ضروراپنے دشمن کوماربھگائے گا اورہماری غذاکا سامان پیداہوجائے گا.پرندوں کے مسخر ہونے کے ذکر سے کفار پر عذاب کی پیشگوئی امیر تیمور کے متعلق تاریخ میں آتاہے کہ جدھر وہ جا تاتھا اس کے لشکر کے ساتھ گدھ اڑتے جاتے تھے.کیونکہ جدھر وہ جاتا تھا اس کو دشمن پر فتح حاصل ہوتی تھی اورگدھو ں کو اندرونی شعور سے یہ بات معلوم ہوگئی تھی کہ اس کے ساتھ جانے میں غذا ملتی ہے.غرض پرندوں کا اڑنا درحقیقت محاورہ ہے کسی قوم کی شکست اورہلاکت کے اظہار کے لئے.اوراس جگہ اسی طرف اشارہ کیا گیاہے.قرآن شریف میں بھی آتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ.اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ.تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ(الفیل:۲ تا ۵).یعنی ابرہہ کالشکر جو مکہ پر حملہ کرنے آیاتھااس کو ہم نے ہلاک کردیا اورایسی بھاگڑ پڑی کہ وہ اپنے مردے جنگل میں چھوڑ گئے.جس پر پرندے اکٹھے ہوگئے اوران کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اورپتھروں پر مار مار کر انہوں نے کھائیں.یہ بھی گدھوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مردہ کی بوٹی نوچ کر کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر کھاتے ہیں اورمٹی سے صا ف کرنے کے لئے اُسے پتھر یالکڑی پر مار مارکرکھاتے ہیں.ممکن ہے اس آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہوکہ تم دیکھ چکے ہو اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کی لاشوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پرندوں نے نوچ کر کھایاتھا وہی پرندے آسمان پر اڑ رہے ہیں اورہمارے حکم کے منتظر ہیں.اس وقت تک ہم ہی نے مسلمانوںکو جہاد سے روکا ہواہے.جب یہ جہاد کے لئے نکلیں گے توتمہاراابرہہ کے لشکر کاساحال ہوگا اورایسا ہی ہوا.آیت کے آخر میں اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ کہنے کا مطلب آخر میں فرمایااِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.یعنی اس پیشگوئی پر آج تم کو تعجب آتاہوگا مگر جولوگ ایمان لائے ہیں وہ اس میں خدا تعالیٰ کے نشانات مشاہد ہ کررہے ہیں اورانہیں اس کے وقوع پر کامل یقین ہے.
Page 156
وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اوراللہ(تعالیٰ)نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش کاذریعہ بنایاہے اوراس نے چارپایوں کے چمڑوں سے(بھی ) جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ تمہارے لئے گھر بنائے ہیں جنہیں تم سفر کے وقت ہلکا (پھلکا )پاتے ہو اور(نیز)اپنے قیام کے وقت (ان سے يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ١ۙ وَ مِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَ اَشْعَارِهَاۤ فائدہ اٹھاتے ہو) اوران(جانوروں)کی باریک اُونوں اور(نیز)ان کی موٹی اونوں اوران کے بالوںکوبھی مستقل اَثَاثًا وَّ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ۰۰۸۱ سامان اور ایک وقت تک (کےلئے )عارضی سامان (بنایاہے).حلّ لُغَات.سَکَنًاسَکَنًاسَکَنَ سے مصدر ہے.اورسَکَنَ فُلَانٌ دَارَہٗ کے معنے ہیں اِسْتَوْطَنَھَا وَاَقَامَ بِھَا.اپنے گھر میں قیام پذیر ہوا.سَکَنَ اِلَیْہِ :اِرْتَاحَ اورجب سَکَنَ کاصلہ الیٰ آئے تواس کے معنے ہیں.اُس نے اس کے پاس آرام پایا.نیز اَلسَّکَنُ کے معنے ہیں.کُلُّ مَایُسْکَنُ اِلَیْہِ وَفِیْہِ وَیُسْتَأْنَسُ بِہٖ.ہروہ چیز جس سے انس و آرام حاصل ہو.اَلرَّحْمَۃُ رحمت.اَلْبَرَکَۃُبرکت.(اقرب) بُیُوتٌ کے لئے دیکھو سورۃ حجر آیت نمبر۸۳.تَسْتَخِفُّوْنَھَا تَسْتَخِفُّوْنَھَا اِسْتَخَفَّ سے مضارع جمع مخاطب کاصیغہ ہے.اوراِسْتَخَفَّہُ کے معنے ہیں.اسے ہلکاسمجھا (اقرب).یَوْمَ ظَعْنِکُمْ ظَعْنٌ ظَعَنَ کامصدر ہے اورظَعَنَ (یَظْعَنُ ظَعْنًا)کے معنے ہیں سَارَ.وہ چل پڑا.چنانچہ کہتے ہیں ’’ظَعَنُوْا عَنْ دِیَارِھِمْ ‘‘ کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کرکوچ کرگئے.(اقرب)پس تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ کے معنے ہوں گے.کہ تم کوچ کے وقت انہیں ہلکا سمجھتے ہو.اَصْوَافٌ:اَصْوَافٌ صَوْفٌ کی جمع ہے.بھیڑوں بکریوں کی اُون کوکہتے ہیں اوروَبَرٌ.اونٹوں کی اون کوکہتے ہیں اس کی جمع اَوْبَارٌ ہے.(اقرب) اَشْعَارٌ:اَشْعَارٌ شَعْرٌکی جمع ہے اوراَلشَّعْرُان سب قسم کے بالوں کو کہتے ہیں جو وبر اور صوف کے علاوہ
Page 157
ہوتے ہیں.(اقرب) اَ لْاَثَاثُ:اَ لْاَثَاثُ: مَتَاعُ الْبَیْتِ بِلَاوَاحِدٍ.اثاث کامفرد نہیں آتااورگھر کے سامان پر یہ لفظ بولتے ہیں.وَقِیْلَ ھُوَ مَایُتَّخَذُ لِلْاِسْتِعْمَالِ وَالْمَتَاعِ لَالِلتِّجَارَۃِ.اوربعض نے کہا ہے کہ اثاث ا س سامان کو کہتے ہیں جو استعمال اورفائدہ اٹھانے کے لئے بنایاجاتاہے نہ کہ تجارت کی غرض سے.وَقِیْلَ الْمَالُ کُلُّہُ.اوربعض نے اس کو عام رکھا ہے اورہرقسم کے سامان کو اس میں شامل کیا ہے.(اقرب) تفسیر.یعنی اس وقت تم آرام سے زندگی بسر کررہے ہو.مستقل گھر بھی ہیں اورسفروں کے لئے خیمے بھی ہیں کہ آسانی سے اٹھاسکتے ہو.اورجہاں ڈیرہ لگاناچاہو ڈیرے لگادیتے ہو.اورتجارت کرتے پھرتے ہو.اس انعام کو اپنے اعمال سے کیوں ضائع کرتے ہو.خیموں کے متعلقتَسْتَخِفُّوْنَهَا کہنے کا مطلب خیموں کے متعلق جویہ فرمایا کہ تم انہیں سفراورحضر میں ہلکاپاتے ہو.اس کایہ مطلب ہے کہ سفرکے وقت اٹھانا سہل ہوتاہے.اوراقامت کے وقت گھرکاکھڑاکرنا آسان ہوتاہے.چند منٹ میں جنگل میں شہر بن جاتاہے.چمڑو ں کے خیموں کا ذکر اس لیے کیا کہ عربوں میں انہی کا رواج تھا (تفسیر کبیر از امام رازی زیر آیت ھذا )اور وہ بارش وغیرہ سے اور سردی سے بچانے کے لیے کپڑا کے خیمہ سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں.وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ اوراللہ (تعالیٰ)نے جوکچھ پیدا کیا ہے اس میں اس نے تمہارے لئے کئی سایہ دینے والی چیز یں بنائی ہیں (جن کے نیچے الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَ تم آرام پاتے ہو )اورپہاڑوں میں (بھی )تمہارے لئے پناہ کی جگہیں بنائی ہیں اور(نیز)اس نے تمہارے لئے سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ١ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ کئی (قسم کی)قمیصیں بنائی ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور کئی (قسم کی )قمیصیں (یعنی زرہیں)جو تمہیں
Page 158
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ۰۰۸۲ تمہار ی(آپس کی)جنگ (کی سختی)سے بچاتی ہیں.اسی طرح وہ تم پر اپنے(روحانی )انعام کو(بھی )پوراکرتاہے تاکہ تم (اس کے )کامل فرمانبرداربنو.حلّ لُغَات.اَکْنَانٌ:اَکْنَانٌ کِنٌّ کی جمع ہے اوراَلْکِنُّ کے معنے ہیں :وِقَاءُ کُلِّ شَیْءٍ وَسَتْرُہُ.ہر چیز کاپردہ.اوراس کو محفوظ رکھنے والاجسم.اَلْبَیْتُ:گھر.(اقرب) سَرَابِیْلُ سَرَابِیْلُکے لئے دیکھو سورۃ ابراہیم آیت نمبر۵۱.سَرَابِیْلُ سِرْبَالٌ کی جمع ہے.اَلسِّرْبَالُ: اَلْقَمِیْصُ سربال کے معنی ہیں قمیص.وَقِیْلَ اَلدِّرْعُ اور زرہ کو بھی سربال کہتے ہیں.وَقِیْلَ کُلُّ مَالَبِسَ اور بعض نے اسے عام رکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو پہنی جائے سربال ہے.بَأسٌ بَأسٌ :اَلشِّدَّۃُ فِی الْـحَرْبِ لڑائی کی شدت کو بأس کہتے ہیں.(اقرب) تُسْلِمُوْنَ تُسْلِمُوْنَ اَسْلَمَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے.اوراَسْلَمَ کے معنے ہیں اِنْقَادَمطیع ہوگیا اَسْلَمَ فُلَانٌ:تَدَیَّنَ بِالْاِسْلَامِ.مذہب اسلام میں داخل ہوگیا.اَسْلَمَ الْعَدُوَّ:خَذَلَہُ.دشمن کو رسواکیا.اَسْلَمَ اَمْرَہُ اِلَی اللہِ :سَلَّمَہُ.اپنے معاملے کو اللہ کے سپردکردیا (اقرب)پس لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُوْنَ کے معنے ہوں گے (۱)تاکہ تم کامل فرمانبردار بنو(۲)تم اپنے معاملات کو اللہ کے سپردکرو.تفسیر.اس آیت میں بھی سابق آیت کا مضمون چل رہاہے اورچند اَورانعامات گناتاہے کہ سفر کرتے ہو تو آرام سے درختوں تلے رہتے ہو.پہاڑوں میں آرام کرتے ہو.لباس دئے ہیں جن سے گرمی کی تکلیف سے محفوظ رہتے ہو.اورزرہیں دی ہیں جن کی مدد سے لڑائی میں تمہاری حفاظت ہوتی ہے.یہ سب نعمتیں ا س لئے دی گئی ہیں تاآرام سے رہو اوردشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہو.مگر اب تم اپنے ہاتھو ں سے اس امن کو برباد کرنے لگے ہو اوراللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اُسی کے خلاف استعمال کرناچاہتے ہو.خدا تعالیٰ توچاہتا تھا کہ ان نعمتوں کے شکریہ میں اس کے فرمانبرداربنو.لیکن ہوایہ ہے کہ یہی امن تم کو مغرورکرکے خدا تعالیٰ ہی کے خلاف کھڑارہا ہے.لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُوْنَ کے معنی لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُوْنَ علاوہ ان معنوںکے جواوپر بیان ہوئے ہیں مُسلم کے معنے دوسرے کو شر سے اورتکلیف سے محفوظ رکھنے والے کے بھی ہیں.کیونکہ تُسْلِمُوْنَ اَسْلَمَ سے نکلا ہے جس کامادہ
Page 159
سَلِمَ ہے اوراس کے معنے محفوظ ہوجانے کے ہوتے ہیں.اَسْلَمَ اس کامتعدی ہے.پس اس کے معنے ہوئے جودوسرے کوشراورنقصان سے محفوظ رکھے.عربی زبان کا عام قاعد ہ ہے کہ ہرفعل لازم ثلاثی پرہمزہ زائدکرکے اسے متعدی بنایاجاسکتاہے.عربوں میں عام طور پر گوسَلِمَ کالفظ محفوظ ہوجانے کے معنوں میں استعمال ہوتاہے.لیکن اَسْلَمَ متعدی کے اوراستعمال توہیں مگر سَلِمَ ماد ہ کے ان معنوں سے متعدی کے معنے موجودہ کتبِ لغت سے ثابت نہیں.مگرا سلامی ادب میں ان معنوں کاجوعربی لغت کے عام قاعد ہ کے روسے جائز ہیں استعمال ثابت ہے.مسلم کے معنی حدیث میں حدیث میں ہے اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِہٖ وَیَدِہٖ( مسلم کتاب الایمان باب بیان تفاضل الاسلام....)مسلمان وہ ہے جس کی زبان سےاورہاتھ سے سب وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اُسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے.میرے نزدیک اس آیت میں یہ معنے بھی مراد ہیں اورمفہوم یہ ہے کہ ان نعمتوں کے دینے کی غرض تویہ تھی کہ تم محفوظ رہو اورخداکے شکر گزاربن کر دوسرے لوگوں کو شر سے محفوظ رکھو مگر تم نے توان نعمتوں کو ظلم کاذریعہ بنالیا ہے.اس آیت سے ایک سیاسی نکتہ بھی نکلتا ہے اوروہ یہ کہ کسی اکثریت کو یہ نہیں چاہیے کہ اقلیت کو ملک سے نکال دے.اس کایہ مطلب نہیں کہ ظالموں کونہ نکالاجائے.جوقوم کسی کے نظام کو توڑتی ہو ان کاتونکالنا ضرور ی ہے مگر مسلمان مکہ والوں کے نظام کو توڑتے نہیں تھے.صرف یہ کہتے تھے کہ آزادی سے ہمیں رَبُّنَااللّٰہُ کہنے دو اورمذہب کے معاملہ میں جبر نہ کرو.مگر باوجود اس کے کہ وہ ان کے نظام میں خلل نہ ڈالتے تھے وہ انہیں ایذادیتے تھے.فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ پس اگر وہ (اب بھی )پھر جائیں تو(اس کی وجہ سےاے نبی تجھ پر کوئی الزام نہیں آئے گا کیونکہ )تیرے ذمہ صر ف الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۰۰۸۳ کھول کر پہنچادینا ہے.تفسیر.یعنی اس مصالحا نہ پیشکش کے بعد بھی اگریہ لوگ اپنے ارادہ سے باز نہ آئیں اوربلاوجہ مسلمانوں کو دکھ دیں توتیراکام توصرف نصیحت ہے وہ تونے کردی.اب یہ اپنے نیک و بد کے خود ذمہ وار ہیں.
Page 160
يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَ اَكْثَرُهُمُ وہ اللہ (تعالیٰ)کے (ا س)انعام کو (بخوبی )پہچانتے ہیں (مگر)پھر (بھی)اس کا انکا رکررہے ہیں اوران میں سے الْكٰفِرُوْنَؒ۰۰۸۴ اکثر توپکے کافر ہیں.حلّ لُغَات.یُنْکِرُوْنَھَا :یُنْکِرُوْنَھَا اَنْکَرَ سے مضارع واحد مذکر غائب کاصیغہ ہے.اس کے معنے کے لئے دیکھو نحل آیت نمبر۲۳.و حجرآیت نمبر ۵۴.تفسیر.یعنی الٰہی نعمتوں کواپنے نفوس میں دیکھتے ہوئے پھر بھی یہ لوگ ناشکری سے کام لے رہے ہیں.یَعْرِفُوْنَ کہہ کر یہ بتایاہے کہ اول توانسان کو محض نعمت کو دیکھ کر ہی نصیحت حاصل کرلینی چاہیے مگر ان کوتو ا س سے بڑا مقام حاصل ہے اوروہ یہ کہ خود ان پر یہ نعمتیں نازل ہیں اوریہ اپنے نفوس میں ان نعمتوں کاوجود پاتے ہیں.مگرپھر بھی ان کا انکار کرتے جاتے ہیں.یعنی عملاً ان کی ناقدری کرتے ہیں یہ مراد نہیں کہ لفظاً انکار کرتے ہیں.کیونکہ منہ سے تو کفار بھی کہتے تھے کہ یہ نعمتیں ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں.يُنْكِرُوْنَهَاکے بعد اَکْثَرُھُمُ الْكٰفِرُوْنَکہنے کی وجہ آخر میں فرمایا وَاَکْثَرُھُمُ الْكٰفِرُوْنَ.اس کے یہ معنے نہیںکہ ان میں سے اکثر منکر ہیں کیونکہ یہ معنی توثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا میں آچکے ہیں.نیز یہاں یہ الفاظ نہیں فرمائے کہ اَکْثُرُھُمُ کَافِرُوْنَ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اَکْثَرُھُمُ الْكٰفِرُوْنَ.حالانکہ خالی یہ بات کہنے کے لئے کہ یہ کافر ہیں اس قدر کہنا کافی تھا کہ اَکْثَرُ ھُمُ کٰفِرُوْنَ.الف لام کی زیادتی کی ضرورت نہ تھی.لفظ کَافِرُوْنَ پر الف لام لانے کی وجہ پس الف لام کی زیادتی زائد مفہوم پیداکرنے کے لئے ہے جواس موقعہ پر کامل کے معنے دیتا ہے.پس اَکْثَرُھُمُ الْكٰفِرُوْنَ کے معنے ہیں وہ پکے منکر ہیں.یعنی انکا ر عام نہیں بلکہ بڑاشدید ہے اوراصرار کے ساتھ ہے.الف لام کایہ مفہوم قواعدنحوسے ثابت ہے.کہتے ہیں اَنْتَ الرَّجُلُ.تو کامل مرد ہے (اقرب الموارد زیر لفظ ال)یہی وجہ ہے کہ یُنْکِرُوْنَھَا میں توسب کوشامل رکھا تھا اوراس جملہ میں اَکْثَرُھُمْ کالفظ استعمال فرمایا یہ بتانے کے لئے کہ یہ قوم ساری ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کررہی ہے.مگران میں سے اکثر تواس انکار میں حد سے بڑھ گئے ہیں گویا قوم کی اکثریت میں عناد اورانکار کا ماد ہ شدت سے پیداہوگیا ہے.
Page 161
ترتیب مضمون کے لحاظ سے اس آیت کے معنی ترتیب مضمون کو مدنظررکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ ایک طرف تودنیوی نعمتوں کوتسلیم کرتے ہیں دوسری طرف روحانی نعمتوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں.گویا اعتراف کالفظ دنیوی نعمتوں کے متعلق ہےجن کااقرار کرتے تھے اور یُنْکِرُوْنَھَا میں روحانی نعمتوں کا ذکر ہے جن کاوہ انکا ر کرتے تھے.وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ اور(اس دن کو بھی یاد کرو)جس دن ہم ہرایک قوم میں ایک گواہ کھڑاکریں گے پھر (اس وقت )ان لوگوں کو جنہوں لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ۠۰۰۸۵ نے کفر (کاطریق)اختیارکیا ہے (عذرخواہی یاتلافی کی )اجازت نہیں دی جائے گی اورنہ (ہی)ان کاکوئی عذر قبول کیا جائے گا.حلّ لُغَات.شَھِیْدٌ شَھِیْدٌکے معنے ہیں اَلشَّاھِدُ.گواہ.اَ لْاَمِیْنُ فِیْ شَھَادَتِہِ.ٹھیک ٹھیک گواہی دینے والا.(اقرب) یُسْتَعْتَبُوْنَ یُسْتَعْتَبُوْنَ اِسْتَعْتَبَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِسْتَعْتَبَہٗ کے معنے ہیں.اَعْطَاہُ الْعُتْبیٰ.اس سے راضی ہوگیا.وَطَلَبَ اِلَیْہِ اَیْ مِنْہُ الْعُتْبیٰ.اس کی رضاء چاہی.چنانچہ کہتے ہیں.’’اِسْتَعْتَبْتُہٗ فَاعْتَبَنِیْ‘‘اَیْ اِسْتَرْضَیْتُہٗ فَاَرْضَانِیْ میں نے اس کی خوشنودی چاہی تووہ مجھ سے خوش ہوگیا.اورانہی معنوں میں یہ فقرہ استعما ل ہوتا ہے کہ مَابَعْدَالْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ اِیْ اِسْتَرْضَاءٌ.موت کے بعد کوئی طلب رضا نہ ہوگی.اَلْعُتْبیٰ:اَلرِّضَا.عتبیٰ کے معنے رضامندی (اقرب)اَلْاِسْتِعْتَابُ اَنْ یَّطْلُبَ مِنَ الْاِنْسَانِ اَنْ یَّذْکُرَ عَتْبَہُ لِیُعْتَب.اِسْتِعْتَابٌ جو اِسْتَعْتَبَ کامصدرہے کے معنے ہیں کہ کوئی عذر بیان کرے تاکہ اس سے ناراضگی دور ہوسکے (مفردات)پس وَلَاھُمْ یُسْتَعْتَبُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ ان کاکوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا(۲)ان کو رضاجوئی کاموقعہ نہ دیاجائےگا.تفسیر.اس جرمِ عظیم کے ذکر کے بعدپھر اُخروی زندگی کاحوالہ دیا کہ اس دنیا میں تواس جرم کی سزاملے ہی گی مگرآخر ت میں یہ اوربھی زیاد ہ سزاپائیں گے اوروہ سزااور ذلت بہت سخت ہوگی کیونکہ تمام ارواح انسانی خواہ
Page 162
ان کے اجسام کسی زمانہ میں کیوں نہ دنیامیں رہے ہوںجمع کی جائیں گی اورہرقوم کانبی سامنے لایاجائے گااوراپنی قوم کے متعلق گواہی دےگا.پھر کیوں یہ لوگ اس ذلت کا جو اس وقت ان کو نصیب ہوگی خیال نہیں کرتے.ایک دوسری جگہ اس ذلت کا مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر فرمایا ہے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَآءِ شَهِيْدًا.يَوْمَىِٕذٍ يَّوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ(النساء :۴۳،۴۴)یعنی جب سب اقوام اورنبی جمع ہوں گے ا س وقت ان کو ایسی ندامت ہو گی کہ یہ خواہش کریں گے کہ زمین پھٹ جائے اورہم اس میں دفن ہوجائیں.ہر قوم میں نبی کے مبعوث ہو نے کا ثبوت اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرقوم میں نبی مبعوث فرمائے ہیں.قرآن کریم نے یہ عقیدہ مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے اورا س میں وہ دوسرے سب مذاہب سے منفرد ہے اوریہ اس کی صداقت کے ثبوتوں میںسے ایک زبردست ثبوت ہے.کافروں کو اذن نہ دیئے جانے کا مطلب یہ جو فرمایا کہ کافروں کو اس وقت اذن نہ دیاجائے گا اس کے معنے بعض نے یہ کئے ہیں کہ انہیں بولنے کا اذن نہ دیاجائے گا (تفسیر مظہری زیر آیت ھذا).یہ معنے درست نہیں کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ کفار قیامت کو اللہ تعالیٰ سے کلام کریں گے.اوراپنے عذرات بھی پیش کریں گے.پس اسلَا يُؤْذَنُ سے مرا د یاتوجنت میں دخول کی اجازت ہے اوریا اس کے معنے شفاعت کے ہیں اورمراد یہ ہے کہ جب نبی حشر کے دن آئیں گے اوران کو اپنی قو م کے ان افراد کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی جوگوپوری طرح کامل نہ ہوئے تھے مگر اس کے قابل تھے کہ نبی انہیں اپنا کہہ سکیں اس وقت یہ لوگ شفاعت سے محروم رہ جائیں گے اوران کے حق میں شفاعت کی اجازت نہ دی جائے گی.شفاعت کے لئے اذن ضروری ہے قرآن کریم اورحدیث سے شفاعت کے متعلق ثابت ہے کہ اذن سے ہوتی ہے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَاتَنْفَعُ الشَّفَاعَۃُ عِنْدَہٗ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَہٗ(سبا :۲۴)یعنی شفاعت صرف انہی کوفائدہ دے گی جن کے حق میں اذن الٰہی ہوگا.سورۃ یونس رکوع۱.طہ رکوع ۶اورالنجم رکوع ۲ میں بھی یہ مضمون بیان ہواہے اورسور ۃبقرہ رکوع ۳۴ میں بھی.حدیث میں بھی شفاعت کے متعلق اذن کالفظ آتاہے.مسند احمد حنبل جلد ۵صفحہ ۴۳پر ابوبکرۃ کی روایت میں ہے ثُمَّ یُؤْذَنُ لِلْمَلٰٓئِکَۃِ وَالنَّبِیِّیْنَ وَالشُّھَدَاءِ اَنْ یَّشْفَعُوْا.یعنی پھر فرشتوں ،نبیوں اورشہداءکو اللہ تعالیٰ اجازت دےگاکہ وہ شفاعت کریں.قرآن کریم میں ایک اور مفہوم بھی اس اذن کابیان ہواہے.سورۃ المرسلات میں ہے وَلَا یُؤْذَنُ لَھُمْ
Page 163
فَیَعْتَذِرُوْنَ.یعنی کفار کوایسی اجازت نہ دی جا ئے گی کہ وہ عذر پیش کرسکیں یعنی ایسی کوئی اجاز ت انہیں نہ ملےگی کہ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ کوئی معقول عذر پیش کرسکیں.قیامت میں انبیاء کی شہادت سے مراد یہ جوفرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء بطورگواہ کھڑے کئے جائیں گے میرے نزدیک انبیاء کی شہادت سے مراد ان کا نمونہ ہے کہ وہ اپنے نمونے کوپیش کریں گے کہ کلام الٰہی نے ہم پر یہ اثر کیا ہے.اس تعلیم کو ماننے کایہ نتیجہ ہواکہ ہمیں خدامل گیا اورہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے.اس طرح پر خدا تعالیٰ اس وقت کافروں کو شرمند ہ کر ے گاکہ دیکھو ہماری کلام کااعجاز جس سے روحانی قوتیں حاصل کرکے ہمارایہ نبی اس کمال تک پہنچ گیا اور تم اس کلام کاانکار کرکے کہاں سے کہا ںجاگرے.نبی اور کلام الٰہی میں تلازم ہرنبی کلام الٰہی کے نتیجے کاعملی نمونہ ہوتاہے یہی وجہ ہے کہ کلام بغیر نبی کے نہیں آتا.نبی سے کلام کی شان کاپتہ لگتاہے اورکلام سے نبی کی شان کا.وَ اِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لَا اورجن لوگوں نے ظلم (کاطریق اختیار)کیا ہے وہ جب اس (موعود )عذاب کو دیکھیں گے تو(اس وقت)نہ (تو)وہ هُمْ يُنْظَرُوْنَ۰۰۸۶ (عذاب)ان پر سے ہلکا کیا جائے گااورنہ (ہی)انہیں مہلت دی جائے گی.حلّ لُغَات.یُنْظَرُوْنَ.وَلَاھُمْ یُنْظَرُوْنَ اَنْظَرَ سے مضارع جمع مذکر مجہول کاصیغہ ہے اور اس کے معنے ہیں ان کو مہلت نہ دی جائے گی.مزید تشریح کے لئے دیکھو حجر آیت نمبر۹.اَنْظَرَہُ الدَّیْنَ:اَخَّرَہٗ.قرض اداکرنے کے لئے قرض دار کومزید مہلت دی.یُقَالُ کُنْتُ اَنْظُرُ الْمُعْسِرَ اَیْ اَمْھِلُہُ یعنی کُنْتُ اَنْظُرُ الْمُعْسِرَکافقرہ انہی معنوں کے لئے استعمال ہوتاہے کہ میں تنگدست قرض دار کو مہلت دیاکرتاتھا.(اقرب) تفسیر.اس جگہ عذاب سے مراد اُخروی عذاب ہے.
Page 164
َ اِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اورجن لوگوں نے (اللہ تعالیٰ کے )شریک بنائے ہیں جب و ہ(ان)اپنے (بنائے ہوئے )شریکو ں کو دیکھیں گے شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ١ۚ فَاَلْقَوْا توکہیں گے (کہ)اے ہمارے رب یہ ہمارے (بنائے ہوئے )شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکاراکرتے اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَۚ۰۰۸۷ تھے جس پر وہ (بڑی جلد ی سے)انہیں کہیں گے (کہ)تم یقیناًجھوٹے ہو.حلّ لُغَات.مِنْ دُوْنِکَ دُوْنَ کالفظ عربی میں آٹھ معنوں میں مستعمل ہوتاہے (۱) فَوْقَ (یعنی بلند ہونے )کے مخالف معنے دیتاہے کہتے ہیں.ھُوَدُوْنَہُ اَیْ اَحَطُّ مِنْہُ رُتْبَۃً.کہ وہ اس سے رتبہ میں کم ہے (۲)ظرف کے طور پر استعمال ہوتاہے اورا س کے معنے اَسْفَلَ(یعنی نیچے ہونے )کے ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں ھٰذَادُوْنَ ذَاکَ اَیْ مُتَسَفِّلٌ عَنْہُ.یہ اس سے نیچے واقع ہے.(۳) اَمَامَ(یعنی آگے)کے معنوں میں استعمال ہوتاہے کہتے ہیں مَشٰی دُوْنَہُ اَیْ اَمَامَہُ وہ اس کے آگے آگے چلا.(۴) وَرَاءَ( پیچھے )کے معنوں میں استعمال ہوتاہے جیسے کہتے ہیں قَعَدَ دُوْنَہُ اَیْ وَرَاءَ ہٗ.وہ اس کے پیچھے بیٹھا.(۵)اور کبھی دُوْنَ کے معنے فَوْقَ (یعنی بلند ہونے )کے ہوتے ہیں.گویایہ لفظ اضداد میں سے ہے (۶)اس کے معنی غَیْرٌ(یعنی سواء)کے بھی ہوتے ہیں.(۷)اس کے معنی شریف (اعلیٰ درجہ) کے ہوتےہیں.(۸)کسی چیز کے خَسِیْسٌ ہونے کے ہوتے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں شَیْءٌ دُوْنٌ اَیْ خَسِیْسٌ کہ یہ چیز کم درجہ کی ہے (اقرب)علاوہ ازیں کہتے ہیں.حَالَ الْقَوْمُ دُوْنَ فُلَانٍ اَیْ اِعْتَرَضُوْابَیْنَہٗ وَبَیْنَ مَنْ یَطْلُبُہٗ فَلَمْ یَقْدِرْ اَنْ یَنَا لَہُ.یعنی فلاں کے درمیا ن قوم حائل ہوگئی اوراس کو اس کے تلا ش کرنے والے سے بچالیا.(اقرب) اَلْقَوْااَلْقَوْااَلْقٰی سے جمع کاصیغہ ہے اوراَلْقَاہُ اِلَی الْاَرْضِ کے معنے ہیں طَرَحَہٗ.اس کوزمین پر پھینکا اور أَلْقَی اِلَیْہِ الْقَوْلَ وَبِالْقَوْلِکے معنے ہیں.اَبْلَغَہٗ اِیَّاہُ اس کو کوئی بات پہنچا دی.اَلْقَی عَلَیْہِ الْقَوْلَ: اَمْلَاہُ.اُسے کوئی بات لکھادی.اَلْقَی اِلَیْہِ السَّمْعَ:اَصْغٰی.اس کی بات توجہ سے سنی (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو
Page 165
نحل آیت نمبر۱۶.پس اَلْقَوْا اِلَیْہِمُ الْقَوْلَ کے معنی ہوں گے وہ ان کو جلدی سے کہیں گے.تفسیر.اَلْقَی اِلَیْہ القَوْلَ کے معنے ہیں کہ اس کی طرف جواب پھینکا.اورپھینکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ فوراً ان کے منہ پرجواب الٹاکر ماریں گے کہ بس جھوٹ نہ بولو.کفر اور گناہ کی دوستی کبھی پکی نہیں ہو سکتی یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں ان کی خاطر یہ لوگ نبیوں سے لڑا کرتے تھے.مگر قیامت کو خدا تعالیٰ سے کہیں گے کہ ان معبودوں کو پکڑو کہ یہی ہم کو گمراہ کرتے تھے.ا س میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کفرو گنا ہ کی دوستی کبھی پکی نہیں ہوتی.کیونکہ انسان ایک حد تک دوسرے کی خاطر تکلیف اٹھاسکتاہے.حد سے زیاد ہ نہیں.پس کفر کی وجہ سے چونکہ مختلف عذاب آتے رہتے ہیں درمیا ن میں ایسے مواقع بھی آتے رہتے ہیںجب اس دوستی کی حد ختم ہوجاتی ہے اورایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار شروع ہوجاتا ہے.یہ جو فرمایا فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اس کے معنے ایک تواچھی طرح کہنے کے ہوتے ہیں.کہتے ہیں اَلْقَی اِلَیْہِ الْقَوْلُ:اَبْلَغَہُ.اس تک بات پہنچا دی ان معنوں کے روسے ترجمہ یہ ہوگاکہ وہ خو ب زور سے انہیں کہہ دیں گے.نیز القی کے معنے پھینکنے کے بھی ہیں اورپھینکنے کے لفظ میں جلد ی کامفہوم پایا جاتا ہے.پس اَلْقَوْا اِلَیْہِمُ الْقَوْلَ کے یہ معنے بھی ہیں کہ وہ فوراً جوا ب دیں گے.فَلَایُخَفَّفُ عَنْھُمْ سے بتایا کہ یہ عذر ان کا غیر معقول ہے اگر کسی نے گمراہ کیا تھا تووہ گمراہ ہوئے کیوں ؟کیوں نہ ورغلانے والے کی بات کو رد کیا.وَ اَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَىِٕذِ ا۟لسَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا اور(ا س حالت کو دیکھ کر )وہ (ظالم جلدی سے )اللہ(تعالیٰ)کے حضور(اپنی )اطاعت کا اظہار کریں گے اورجو کچھ يَفْتَرُوْنَ۰۰۸۸ و ہ اپنے پا س سے گھڑا کرتے تھے وہ (سب ان کے ذہنوں سے )غائب ہوجائے گا.حلّ لُغَات.السَّلَمَ السَّلَمَکے لئے دیکھو نحل آیت نمبر۲۹.ضَلَّ عَنْھُمْ ضَلَّ عَنْھُمْکے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۳۱.ضَلَّ یَضِلُّ ضِدّ اِھْتَدٰی یعنی ہدایت کے خلاف حالت پر ہو گیا.اور دین اور حق کو نہ پایا.ضَلّ عَنْہُ
Page 166
یَضَلُّ: لَمْ یَھْتَدِ اِلَیْہِ.اس طرف راہ نہیں پائی.ضَلَّ یَضَلُّ (ضاد کی زبر سے) فُلَانٌ الطَّرِیْقَ وَ عَنِ الطَّرِیْقِ: لَمْ یَھْتَدِ اِلَیْہِ.راستہ نہ پایا.یہی معنی ہوتے ہیں.جب داریا منزل یا ہر اپنی جگہ پر قائم رہنے والی چیز کا اس کے بعد مذکور ہو.ضَلَّ الرَّجُلُ فِی الدِّیْنِ ضِلَالًا وَضَلَالَۃً: ضِدُّ اِھْتَدٰی.اس شخص نے دین کے معاملہ میں درست راہ نہیں پائی.ضَلَّ فُلَانٌ الْفَرَسَ.اس کا گھوڑا کھویا گیا.ضَلَّ عَنّیْ کَذَا: ضَاعَ.ضائع ہو گیا.ضَلَّ الْمَاءُ فِی اللَّبَنِ :خَفٰی وَ غَابَ.پانی دودھ میں مل گیا.اور غائب ہو گیا.ضَلَّ فُلَانٌ فُلَانًا: نَسِیَہُ.اس شخص کو بھول گیا.ضَلَّ النَّاسِی: غَابَ عَنْہُ حِفْظَ الشَّیْءِ بھول گیا.اس کے ذہن سے بات نکل گئی.ضَلَّ سَعْیُہُ: عَمِلَ عَمَلًا لَمْ یَعُدْ عَلَیْہِ نَفْعُہُ.ایسا کام کیا جس کا اسے کوئی نفع نہ ہوا.(اقرب) یَفْتَرُوْنَ یَفْتَرُوْنَ اِفْتَرٰی سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اور اِفْتَرٰی عَلَیْہ الْکَذِبَ کے معنے ہیں : اِخْتَلَقَہٗ.اس کے خلاف جھو ٹ بنالیا (اقرب)پس ضَلَّ عَنْہُمْ مَّاکَانُوْا یَفْتَرُوْنَ کے معنے ہوں گے جو وہ گھڑا کرتے تھے ضائع ہوجائے گا.تفسیر.قیامت کے دن کفار کی لجاجت اپنے معبود ان کے سامنے یعنی جب کفار دیکھیں گے کہ آج تووہ بھی ہمارے دشمن ہو رہے ہیں جن کی ہم عبادت کیاکرتے تھے تووہ جلد ی سے اپنے رویہ کو بدل کر لجاجت سے باتیں کرنی شروع کردیں گے اورکہیں گے کہ ہم توآپ ہی کے بندے ہیں یہ عبادت وغیرہ توصر ف توجہ کے قیام کے لئے تھی یاہم یہ کام نیک نیتی سے سچ سمجھ کرکرتے تھے کو ئی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا منشاء نہ تھا اورجو بڑے بڑے دعوے وہ دنیا میں کرتے تھے سب غائب ہوجائیں گے.اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا جن لوگوں نے (خود بھی )کفر(کاطریق )اختیار کیا ہے اور(دوسروں کو بھی )اللہ (تعالیٰ ) کی راہ سے روکاہے ا ن فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ۰۰۸۹ کو ہم اس عذاب سے بڑھ کر ایک اورعذاب دیں گے کیونکہ وہ (ہمیشہ )فساد (کے کام )کرتے تھے حل لغات.اَلْفَوْقُ:اَلْفَوْقُ فَاقَ کامصدر ہے.جس کے معنے بلند ہونے کے ہیں.اصل میں یہ
Page 167
ظرف مکان ہے جیسے کہتے ہیں صَعَدْتُ فَوْقَ الْجَبَلِکہ میں پہاڑ پر چڑھا.اور کبھی کبھی ظرف زمان کے لئے بھی استعمال ہوتاہے چنانچہ کہتے ہیں لَبِثْنَافَوْقَ شَھْرٍ اَیْ زَمَانًا اَکْثَرَ مِنْ شَھْرٍ.ہم ایک ما ہ سے زائد ٹھہرے.یہ معر ب ہوتاہے.لیکن جب اس کامضاف الیہ حذف ہو.اورمعنیً وہ ذہن میں ہوتواس وقت یہ مبنی ہوتاہے.اوراس کے آخر پر ضمّہ آتاہے.چنانچہ کہتے ہیں عِنْدِیْ مِائَۃٌ فَمَافَوْقُ.کہ میرے پاس سوسے اوپر چیزیں ہیں.یہاں فوق کے بعد مضاف الیہ حذف ہے.اوراگر مضاف الیہ بولاجائے تووہ معرب ہوتاہے.اور کبھی کبھی فوق کالفظ بطور اسم کے استعمال ہوتاہے.اوربعض اوقات زیادتی کے بیان کے لئے استعمال کیا جاتاہے.چنانچہ کہتے ہیں اَلْعَشْرَۃُ فَوْقَ التِّسْعَۃِ اَیْ تَزِیْدُعَلَیْھَا.دس نوسے زیادہ ہوتے ہیں.علاوہ ازیں کہتے ہیں ھَذَافَوْقَ ذَاکَ اَیْ اَفْضَلُ مِنْہُ.کہ یہ اُس سے افضل ہے.(اقرب) تفسیر.گمراہ کرنے والے کو قیامت کے دن زیادہ سزا ملے گی اس آیت میں پھر وہی فرق بتایا کہ کافر دو قسم کے ہیں ایک گمراہ اورایک گمراہ کرنے والے.اوریہ بھی بتایا ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو دوسروں سے زیادہ سزاملے گی.لطف یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ دنیا میں جاہلو ںسے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری نجات کے ذمہ وار ہیں لیکن وہاں جن کی نجا ت کے ذمہ وار بنتے تھے ان سے بھی زیادہ انہیں سزاملے گی.وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اور(اس دن کو بھی یاد کرو)جس دن ہم ہر ایک قوم کے اند ران کے خلاف خود انہی میں سے ایک گواہ کھڑاکریں گے اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ١ؕ وَ نَزَّلْنَا اور(اے رسول)تجھے ہم ان(سب)کے خلاف گواہ بناکر لائیں گے اورہم نے یہ کتا ب ہرایک بات کو کھول کر عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بیان کرنے کے لئے اور(تمام لوگوں کی)رہنمائی کے لئے اور(ان پر)رحمت کرنے اور کامل فرمانبرداری اختیار
Page 168
بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۠ؒ۰۰۹۰ کرنےوالوں کو بشارت دینے کے لئے اُتاری ہے.حلّ لُغَات.تِبْیَانًا تِبْیَانًا یہ بَانَ کامصدر ہے.اوربَانَ الشَّیْءُ(یَبِیْنُ تِبْیَانًا)کے معنے ہیں.اِتَّضَحَ.کوئی چیز واضح ہوگئی اوربَانَ کافعل لازم ہے لیکن کبھی کبھی متعدی بھی استعمال ہوتاہے.(اقرب) تفسیر.قیامت کے دن آنحضرت ؐ کی شہادت سے مراد آپ کا نمونہ پیش کر نا ہے اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کو مکمل کیا گیا ہے.فرماتا ہے جب سب نبی اپنے اپنے نمونہ کو پیش کریں گے ا س وقت توبھی ان لوگوں پر بطور گواہ پیش ہوگااورہم تجھے دکھا کر ان سے پو چھیں گے کہ یہ بھی توتم میں سے ایک تھایہ کیوں شرک وغیر ہ بدعقائد میں نہ پھنسا.اورکیوں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بن کر دوسروں کی ہدایت کاموجب ہو ا.کیا اسی وجہ سے نہیں کہ اس پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہواتھا اور تم اس سے محرو م تھے بلکہ اس کلام کی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے.اس کے بعد اس وحی کی برکات کی طرف اشار ہ فرمانے کے لئے فرماتا ہے.ا ے محمدؐ ہم نے تجھ پر و ہ کتاب اتاری ہے جس میں ہرروحانی ضرورت کی تشریح ہے اوراس میں رحمت اورہدایت کے سامان ہیں.یعنی تجھ میں اورتیری قوم کے لوگوں میں جو فرق ہے وہ اسی کلام کی وجہ سے ہے.قرآن کریم میں ہر چیز کے اصول موجود ہیں یہاں کُلِّ شَیْءٍ سے دنیا کی ہرچیز مراد نہیں بلکہ وہ چیزیں مراد ہیں جو اسی کتاب سے مناسبت رکھتی ہیں.کوئی استاد اگراپنے شاگرد کو کہے کہ ساری کتب اٹھالائو تواس کایہ مطلب نہیں ہوتاکہ وہ لائبریری کی سب کتب اُٹھالائے.بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوگاکہ اپنی کتب اٹھالائو ایسا ہی یہاںپرکل سے مراد وہ چیزیں ہیں جوروحانیت کی ترقی کے لئے ضروری ہیں.اگر کوئی کہے کہ بعض مسائل کی تفصیل صرف احادیث میں ملتی ہے.تواس کا جواب یہ ہے کہ اصول سب قرآن کریم میں بیان ہیں جوتفاصیل احادیث میں ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے قرآن کافہم سب سے زیاد ہ دیاتھا.وہ قرآن کریم سے جو مطالب اخذ کرتے تھے ہم نہیں کرسکتے.پس اگر آپ نے قرآنی مطالب کی بعض تفاصیل بیان کی ہیں تواس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم نامکمل ہے بلکہ اس کے صر ف یہ معنے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کامل فہم سے ان مسائل کاقرآن سے استنباط کیا.گوہماراذہن اس باریکی کو نہیں پاسکا.
Page 169
اہل قرآن کو غلطی لگنے کی وجہ اہل قرآن کہلانے والوں کو اس مسئلہ میں سخت غلطی لگی ہے.وہ کہتے ہیں کہ محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے آدمی تھے ان کی بات کیوں مانیں جوقرآن کریم میں ہے وہ مانیں گے حالانکہ رسول کریم ؐ کی بات کے ماننے کاسوال نہیں بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ ہم سے قرآن کریم کو زیادہ سمجھتے تھے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَایَنْطِقُ عَنِ الْھَوٰی اِنْ ھُوَ اِلَّا وَحْیٌ یُّوْحٰی(النجم :۴،۵)رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے متعلق جو کچھ فرماتے تھے وحی الٰہی کے مطابق فرماتے تھے غلطی نہیں کرتے تھے.پس جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اس کے فہمِ قرآن کو دوسروں کے فہم پر مقد م کیا جائے گا.ہمارایہ حق ہے کہ یہ بحث کریں کہ یہ حدیث صحیح نہیں.مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث توصحیح ہے مگررسول کریم صلعم نے غلطی کی.نعو ذ باللہ من ذالک قرآن کریم کی تعلیم کے بارہ میں آپؐ کی تفسیر اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی توبھی آپ ہی کی تفسیر کو ہمیں صحیح ماننا پڑے گا.بشرطیکہ جس حدیث میں و ہ مذکور ہے وہ صحتِ احادیث کے اصول پر پوری اترتی ہو.قرآن کریم کے چار کام اس جگہ قرآن کریم کے چار کام بتائے ہیں (۱)تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ہے یعنی سب ضروری امورروحانیہ کی تشریح اس میں موجود ہے (۲) ہدایت ہے (۳)رحمت ہے.(۴)مومنوں کے لئے بشارت ہے.اگلی آیات میں ان مطالب کی تشریح کی گئی ہے.اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ اللہ (تعالیٰ)یقیناً عدل کا اوراحسان کا اور(غیر رشتہ داروںکوبھی)قرابت والے(شخص)کی طر ح(جاننے ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ١ۚ اورمدد)دینے کاحکم دیتاہے اور(ہرایک قسم کی)بے حیائی اورناپسندیدہ باتوں اوربغاوت سے روکتاہے.وہ تمہیں يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۰۰۹۱ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جائو.حلّ لُغَات.اَلْعَدْلُ اَلْعَدْلُ عَدَلَ کامصدر ہے اورعَدَلَ(یَعْدِلُ)فُلَانًا بِفُلَانٍ کے معنے ہیں.سَوّٰی بَیْنَھُمَا.دونوں کے ساتھ برابر کاسلوک کیا.عَدَلَ الْقَاضِیْ وَالْوَالِیْ (عَدْلًا وَعَدَالَۃً)قاضی نے انصاف
Page 170
کیا.نیز اَلْعَدْلُ کے معنے ہیں.ضِدُّ الْجَوْرِ.انصاف.اَلْعَادِلُ اَلْمَرِضِیُّ لِلشَّھَادَۃِ.درست گواہی دینے والا.راستباز.اَلْعَدْلُ مِنَ الْقُضَاۃِ وَالْحُکَّامِ.اَلْوَافُوْنَ لِلْحَقِّ فی اَحْکَامِھِمْ.وہ حکام اورقاضی جودرست فیصلے کرنے والے ہوں.(اقرب) اَلْاِحْسَانُ اَلْاِحْسَانُ اَحْسَنَ سے مصدر ہے اوراَحْسَنَ کے معنے ہیںاٰتَی بِالْـحَسَنِ.پسندیدہ کام کیا.اَحْسَنَ الشَّیْءَ جَعَلَہُ حَسَنًا.کسی چیز کو عمدہ بنادیا.عَلِمَہُ.کسی چیز کوجانا.اورانہی معنوں میں یہ فقرہ بولاجاتا ہے کہ فُلَانٌ یُحْسِنُ الْقِرَاءَ ۃَاَیْ یَعْلَمُھَا.فلاں شخص اچھی طرح پڑھنا جانتاہے(اقرب) اَلْقُرْبیٰ: اَلْقُرْبُ فِی الرَّحْمِ.رشتہ داری.(اقرب) اَلْفَحْشَائُ: اَلْفَاحِشَۃُ.سخت قباحت والاگناہ یاہر وہ بات جس سے اللہ نے روکا ہے.اَلْبُخْلُ فِی اَدَاءِ الزَّ کٰوۃِ.زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل.(اقرب) اَلْمُنْکَرُ اَلْمُنْکَرُ اَنْکَرَ سے اسم مفعول ہے (اس کےلئے دیکھو حجرآیت نمبر۶۳)نیز اس کے معنے ہیں مَا لَیْسَ فِیْہِ رِضَی اللہِ مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ.وَالْمَعْرُوْفُ ضِدُّہُ.ناپسندیدہ بات یا فعل.معروف اس کے مخالف معنے دیتا ہے.(اقرب) تَذَکَّرُوْنَ:تَذَکَّرُوْنَ تَذَکَّرَسے جمع مخاطب کاصیغہ ہے اورتذکّر کے وہی معنے ہیں جو ذَکَرَ کے ہیں.ذکر کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر۲۰.یَتَذَکَّرُ.تَذَکَّرَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور تَذَکَّرَ کے معنے ہیں ذَکَرَ الشَّیْءَ وَحَفِظَہُ فِی ذِھْنِہِ.کسی چیز کو ذہن میں محفوظ کیا یعنی یاد کیا.مَاکَان قَدْنَسِیَ.فَطِنَ بِہٖ بھولی ہوئی بات کو بیان کیا.اَللہ مَـجَّدَہُ وَسَبَّـحَہُ.اللہ کی بزرگی بیان کی اور اس کی تسبیح کی.(اقرب) تفسیر.پچھلے رکو ع کے آخر میں دعویٰ کیاگیاتھا وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۠.یعنی قرآن کریم ان چار خوبیوں کاحامل ہے (۱) تِبْیَانُ لِکُلِّ شَیْءٍ(۲) ھدایت(۳) رحمۃ (۴) بشریٰ للمسلمین.اس رکوع میں اوراگلے رکوعوںمیں اس امر کاثبوت دیاگیا ہے کہ یہ چاروں امور قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں اورا ن کی بناء پر قرآن کریم کے کامیاب ہونے میں کوئی شک نہیں.سب سے پہلا ثبوت یہ آیت ہے اور میرے نزدیک اس آیت میں جومضمون بتایاگیا ہے وہی ان چاروں باتوں کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہے.
Page 171
اس آیت میں تین باتوں کے کرنے کاحکم دیاگیاہے.اورتین باتوں سے رکنے کا حکم دیاگیاہے اوربری باتوں سے روکنا رحمت پردلالت کرتا ہے اوراچھی باتوں کے کرنے کاحکم دینا ہدایت پر دلالت کرتا ہے.یہ آیت قرآن کریم کے جامع ہونے کی بہترین مثال ہے پھر اس میں اخلا قی امورکے سب مدارج کو جمع کردیاگیا ہے جس کی وجہ سے یہ آیت جامع ہو گئی ہے اورتِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍکی بہترین مثال ہے.آیت کو ختم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ پر کیا گیا ہے.تَذَکَّرَ کے وہی معنے ہوتے ہیں جوذَکَرَ کے معنے ہیں پس اس کے معنے یاد رکھنے یا خدا تعالیٰ کی بڑائی کرنے کے ہیں.اورلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ کے معنے ہیں تاتم اللہ تعالیٰ اوربندوں کے حقوق کو یاد رکھو یایہ کہ تاتم اللہ تعالیٰ کی تحمیدو تمجید کرو.اور چونکہ یہی دونوں مقصد ہیں جن کوپوراکرنے کے لئے انسان کو پیدا کیاگیا ہے اس لئے اس آیت میں یہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ اس تعلیم پر چل کر تم اپنی پیدائش کے مقصود کو پالو گے.دیکھو کس قدر چھوٹی سی آیت ہے اورکس طرح اس میں ان سب امور پر روشنی ڈالی گئی ہےجن کا قرآن کریم کی فضیلت کے متعلق دعویٰ کیاگیا ہے.اس ایجاز کے ساتھ ایسی تفصیل قرآن کریم کے سوااور کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی.اورپھر کوئی اغلاق نہیں معمّہ نہیں مضمون صا ف ہے ہرعقلمند ایک ادنیٰ تأ مل سے حقیقت کو معلوم کرسکتا ہے.ا ب میں آیت کے مضمون کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرتاہوں.یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہرایک چیز کے لئے ایک اثبات کاپہلو ہوتاہے اوردوسرانفی کا.کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے دونوں پہلو مکمل نہ ہوں.یعنی جن چیزوں کا اس کی تکمیل کے لئے موجود ہوناضروری ہے وہ اس میں پائی جائیں اورجن چیزوں سے اس کی ذات میں نقص پیدا ہوتا ہوان سے و ہ پا ک ہو.مکمل مذہبی تعلیم کے لئے تین ضروری خصوصیتیں مذہب کو مدنظر رکھتے ہوئے مکمل تعلیم کے لئے مندرجہ ذیل باتوں کا پایا جانا ضروری ہے.۱.یہ کہ وہ ان باتوں کے کرنے کاحکم دے جن سے روحانیت اپنے کما ل کو پہنچ سکتی ہو اوران باتوں سے منع کرے جو اس کمال سے محروم رکھنے والی ہوں.۲.یہ کہ وہ ایساقانون تجویز کرتے وقت جو صرف ایک شخص یاقوم سے تعلق نہ رکھتاہو بلکہ کثیر افراد اورکثیراقوام سے تعلق رکھتاہوان تمام طبائع کا لحاظ رکھے جن کے لئے و ہ وضع کیاگیاہو.اورایسے احکا م دے جن پر ہرشخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق عمل کرسکے.۳.تیسری خصوصیت مکمل تعلیم میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کے احکام بنی نوع انسا ن کے لئے قابل عمل ہوں
Page 172
اوران سے کوئی فساد مذہب میں یااخلاق میں یاعقل میں یاتمدن میں نہ پیدا ہوتاہو.اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تینو ںخوبیوں کو جمع کردیا ہے.دیکھو کتنی چھوٹی سی آیت ہے مگر اس میں تکمیل کے دونوں پہلو(نفی واثبات)کس خوبی اورخوش اسلوبی سے جمع کردئے گئے ہیں.تین باتوں یعنی عدل،احسان اورایتاء ذی القربیٰ کے کرنے کاحکم دیاگیا ہے اورتین باتوں یعنی فحشاء ،منکر اوربغی سے روکاگیا ہے.عدل کے معنی برابری کے ہوتے ہیں یعنی انسان دوسر ے سے ایسا سلو ک یا معاملہ کرے جیساکہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے.اس پرظلم کیا جاتا ہے تووہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا ظلم ہواہے مگر اس سے زیادہ سختی نہیں کرسکتا.اگر اس سے کوئی شخص حسن سلوک کامعاملہ کرتا ہے تواس کابھی فرض ہے کہ کم سے کم اتنا حسن سلوک اس سے کرے.اللہ تعالیٰ سے عدل کے معنی اللہ تعالیٰ سے عد ل کرنے کے یہ معنے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ا س کے ساتھ نیک معاملہ کیا ہے.یہ بھی اس کاحق اداکرے اوراپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کے لئے اعتراضات کے مواقع پیدانہ کرے.اسی طرح یہ کہ ا س کاحق غیر اللہ کو نہ دے اورشرک میں مبتلا نہ ہو کیونکہ شرک کر نا گویا خدا تعالیٰ کاحق چھین کردوسرے کو دینا ہے اوریہ ظلم ہے.اسی وجہ سے قرآن کریم میں شرک کانام ظلم بھی رکھا گیاہے.پس خدا کا بیٹایابیوی یااس کے شریک قرا ردینا عد ل نہیں بلکہ ظلم ہے.کیونکہ ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ ایک کاحق کسی اورکے سپرد کردیاجائے.اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی طرف منسوب کرلینا بھی عدل کے خلاف ہے.مثلاً شریعت کابنانا اورالہا م الٰہی کابھیجنا خدا تعالیٰ کاکام ہے.اب اگر کوئی شخص خود ہی شریعت بنانے کامدعی بن بیٹھے یاالہام نازل کرنے کا جیسا کہ بہاء اللہ وغیر ہ نے کیاتووہ عدل کو توڑتا ہے.اگر انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ عد ل کرے توشرک،کفر اورنافرمانی سب مٹ جائیں.عدل سے بڑھ کر دوسرادرجہ احسان بتایا ہے.احسان کامفہوم یہ ہے کہ یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسراہم سے کیاسلوک کرتاہے بلکہ اگر وہ براسلوک کرتاہے تب بھی ہم اس کے ساتھ اچھا ہی سلو ک کریں.یہ مقام پہلے مقام سے بڑاہے اورعفو،درگذر،غرباء کی مدد،صدقہ و خیرات اورقومی خدمات وغیر ہ نیکیا ں سب ا س کے اند رشامل ہیں.علوم کی ترقی و تدوین کے لئے کوشش کرنابھی اس کے اند ر آجاتا ہے کیونکہ ان کے نتیجہ میں اپنوں اوربیگانوں کو جسمانی اور روحانی فائدہ اورآرام پہنچتا ہے.ایتاء ذی القربیٰ کا درجہ تیسرامقام اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى کا بتایا ہے جس کے معنے ’’رشتہ داروں کو دینا یا رشتہ داروں کادینا ہے ‘‘.اورمطلب آیت کا یہ ہے کہ بنی نوع انسان سے ایساسلوک کرو جیساکہ ایک رشتہ دار
Page 173
دوسرے رشتہ دار سے سلوک کیاکرتا ہے.ماں کی محبت بے لوث ہو تی ہے اس سلو ک سے احسان کا سلوک مراد نہیں کیونکہ احسان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے.اس سلوک سے وہ سلوک مراد ہے جو محبت طبعی کی وجہ سے مبادلہ کے خیال کے بغیر کیا جاتا ہے.احسان کر تے وقت توانسان کو یہ خیال ہوتاہے کہ فلاں شخص نے مجھ سے اچھا سلوک کیا ہے میں ا س سے بہتر بدلہ دوں تامیر ی نیک نامی ہو یاگنہگار کی خطامعاف کرتے ہوئے یہ خیا ل آجاتا ہے کہ میں اس سے حسن سلوک کروں گاتوا س کے دل سے بغض نکل جائے گا اوریہ میرادوست بن کر میری تقویت کاموجب ہو گا.لیکن ماں جو اپنے بچہ سے محبت کرتی ہے اوراس کے لئے قربانی کر تی ہے ا س میں ذرّہ بھر بھی بدلہ کی خواہش نہیں ہوتی.بلکہ اس کی محبت کی بنیا د اس کی اپنی ہی قربانی پر ہوتی ہے ایک عورت کے ہا ں جب اولاد نہیں ہوتی توا س کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتاکہ میرالڑکا ہوتاتووہ میری خدمت کرتا.بلکہ اسے اولاد کی خواہش اس جذبہ کے ساتھ ہوتی ہے کہ میں اسے پالتی،اس کی خدمت کرتی،اسے کپڑے پہناتی،اُسے بیاہتی ،اس کے بچوں کوکھلاتی.غرض اولاد کی خواہش کے وقت ماں کے دل میں خدمت لینے کا ادنیٰ سے ادنیٰ احساس بھی نہیں ہوتا.بلکہ اس خواہش کاموجب اولاد کی خدمت کرنے کاشوق ہوتاہے یہی وہ نیکی کاجذبہ ہے جو انسان کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے.اورجس کے حصول کے بعد انسان کا اخلاقی وجود مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کا مقام حاصل کرنے کے بعد جب کہ تم کو لینے سے زیادہ دینے کی خواہش ہوتی ہے تووہ مقام نیکی کابھی حاصل کرو کہ سب بنی نوع انسان تمہیں اپنے بچے نظر آنے لگیں اوران کی خدمت کا جوش تمہارے دل میں اس طرح موجزن ہو جائے جس طرح ایک ماں کے دل میں اپنے بچہ کی محبت جوش مارتی رہتی ہے.احسان اور ایتاء ذی القربیٰ قرب الٰہی کی دو سیڑھیاں ہیں یہ تعلیم جو اوپر بیان ہوئی ہے اس میں اثباتی تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے اورنہایت مختصر الفاظ میں اخلاق فاضلہ کے سب پہلو ئوں کو بیان کردیاگیاہے.ا س موقعہ پر یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کاحق توعد ل میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شخص احسا ن یا ایتاء ذی القربیٰ کامعاملہ نہیں کرسکتا.مگر بندوں کے ساتھ سلوک کاحکم عدل میں بھی ہے اورپھر احسان و ایتاء ذی القربیٰ میں بھی ہے بلکہ پچھلے دومقامات میں توخالص بندوں ہی کے ساتھ تعلقات سلو ک مراد ہیں.اس میں یہ اشار ہ ہے کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے اوراس کی مرضی کو پانے کے لئے بندوں سے سلوک ضروری ہے.گویا احسان اورایتاء ذی القربیٰ قرب الٰہی کی دوسیڑھیا ں ہیں.
Page 174
فحشاء سے مراد اس اثباتی تعلیم کے بعد نفی کے پہلو کو لیا گیا ہے اوراس میں بھی تین ہی باتوں سے روکا گیاہے.سب سے پہلے فحشاء سے روکاہے اور فحشاء کالفظ جب منکر کے مقابل میںآئے توا س سے مراد صرف وہ بدی ہوتی ہے جس کاعلم صرف ا س کے مرتکب کو ہو،دوسرے کو نہ ہو.اس کے بعد منکر سے روکاہے.منکر سے مراد وہ بدی ہے جو لوگوںکو نظرآتی ہو اوروہ اسے برامحسوس کرتے ہوں.اگرچہ اس کااثر باقی لوگوں کے حقوق پر عملاً بہت کم پڑتاہو.مثلاً گالیاں دیناجھوٹ بولنا وغیرہ یہ سب منکر میں شامل ہیں.پس منکر سے اس لئے منع فرمایا کہ اس سے لوگوں کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے.تیسری بات جس سے روکا ہے وہ بغی ہے یعنی کسی کاحق مارلینا.یہ بدی نہ صر ف لوگوں کو محسوس ہی ہوتی ہے بلکہ اس سے لوگوںکونقصان بھی پہنچتاہے.دنیا کی تمام بدیاں فحشاء منکر اور بغی میں آجاتی ہیں دنیا میں جس قد ربدیاں پائی جاتی ہیں خواہ وہ کسی قسم کی ہی کیوں نہ ہو ں.ان تینوں اقسام میں آجاتی ہیں.یاتوبدی ایسی مخفی ہوتی ہے کہ لوگوں کی نظر سے پوشید ہ رہتی ہے یاایسی ہوتی ہے کہ دوسرے لوگوں کوبھی اس کاعلم ہوجاتا ہے اورانہیں اس سے ذہنی تکلیف پہنچتی ہے اوریا پھر وہ بدی ایسی سخت ہوتی ہے کہ اگر بعض کو اس سے ذہنی تکلیف پہنچتی ہے توبعض دوسروں کے حقوق اس فعل کی وجہ سے تلف ہوجاتے ہیں.ان سب قسم کی بدیوں سے بچنے کااس آیت میں حکم دیاگیا ہے.کامل تعلیم کے لئے تمام فطرتوں کا لحاظ ضروری ہوتا ہے میں نے اوپر بتایا تھا کہ کامل تعلیم کے لئے جو سب ضرورتوں پر حاوی ہو یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں تما م فطرتوں کالحاظ رکھا گیاہو.اس آیت میں جو تعلیم دی گئی ہے اس میں وہ بات بھی موجود ہے کیونکہ دنیا میں بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو فحشاء میں مبتلاہوتے ہیں لیکن ظلم کرنا ہرگز پسند نہیں کرتے اوراسی طرح کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظلم کرکے دوسروں کامال تولے لیتے ہیں مگر جھوٹ سے ان کو نفرت ہوتی ہے اوروہ کسی کا حق مارنا بھی پسند نہیں کرتے مگرشریعت کی بیان کردہ وہ بدیاں جوانسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں یعنی دل میں کسی کا کینہ رکھنا یاعیب جو ئی کرنا یاچغلی کرنا وغیرہ وہ ان میں مبتلاہوتے ہیں.قرآنی تعلیم ہی مکمل تعلیم ہے اللہ تعالیٰ نے تین جامع الفاظ رکھ کر ہرقسم کی بدیوںکو اورسب طبائع کی بدیوں کو شامل کردیا ہے.اورایسا ہی نیکیوں کے ذکر میں بھی ہرقسم کے میلا ن والوں کو جمع کردیا ہے.عدل کو بھی اوراحسان کو بھی اوربلامبادلہ خدمت کرنے کی طاقت کوبھی.
Page 175
نیکی کے حصول اور بدی سے بچنے کا طبعی طریقہ اس کے علاوہ ان مختصر سے الفاظ میں یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ بدی سے بچنے اورنیکی کے اختیارکرنے کاراستہ کون سا ہے.چنانچہ نیکیا ں گناتے ہو ئے نیکی کے نچلے درجے کو پہلے بیان فرمایا ہے پھر اس کے اوپرکے درجہ کو پھر اُس کے اوپر کے درجہ کو.اسی طرح بدیوں کے ذکر کو سب سے پہلے نچلے درجہ کی بدی سے شروع کیاہے پھر ا س سے اوپر کی بدی بیان کی ہے اورپھر اس سے اوپر کی اوراسی طرح انسان کو نیکیوں کے حصول اوربدیوں سے بچنے کاطبعی طریقہ بھی بتادیا ہے.اوروہ یہ کہ جو انسان نیکی کے حصول کے لئے کوشش کرنی چاہے اسے پہلے عدل کا مقام اپنے اندرپیداکرناچاہیے پھر احسان کا پھر ایتاء ذی القربیٰ کا.اسی طرح جو بدیوں سے بچنا چاہے اسے پہلے بغی سے بچناچاہیے پھر منکر سے بچنے کے قابل ہوسکے گااورپھر منکر سے بچنے کی جدوجہد کرنی چاہیے پھر کہیں جا کروہ فحشاء سے بچنے کے قابل ہوگا.اس کے برخلاف اس ترتیب سے اس امر کی طرف بھی رہنمائی کی گئی ہے کہ نیکیوں میں تنزّل کی سیڑھی کون سی ہے.جوانسان ایتاء ذی القربیٰ کے مقام پر ہے اسے اس پر مضبوطی سے قائم ہونا چاہیے ورنہ گر کر احسان کے مقا م پر آجائے گا.اوراحسان پر جو کھڑا ہے اسے اپنے مقام کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ عدل کے مقام پر آگرے گا.اسی طرح اس پر خوش نہ ہونا چاہیے کہ مجھ میں صرف فحشاء پائی جاتی ہیں کیونکہ جو فحشاء کامرتکب ہوتاہے منکر کاارتکاب اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے اورپھر بغی کا.نیکی کرنے کے لئے سب سے پہلے چھوٹی بدی کو پھر بڑی کو چھوڑنا چاہیے غرض ا س بیان میں ترتیب کو مدنظر رکھ کر انسانی ذہن کو اس طرف منتقل کیا ہے کہ نیکی کرنے میں سب سے چھوٹی نیکی پہلے حاصل ہوتی ہے اوربدی کو ترک کرتے ہوئے سب سے بڑی بدی کو پہلے چھوڑاجاتاہے.اس جدوجہد کی مثال سیڑھی کی ہے جو انسان نیکی کی عمارت پر چڑھنا چاہے وہ سب سے پہلے نچلے زینہ پر قدم رکھے گا اورپھر ایک ترتیب سے ترقی کرتا ہوا اوپر تک چڑھ جائے گا.اورجو شخص بدیوں کے مکان پر چڑ ھ چکا ہے اورنیچے اترناچاہتا ہے اسے سب سے پہلا قدم اوپر کے زینہ پر رکھناہو گا.اورپھر و ہ تدریجاً نیچے آتاجائے گا.اسلامی تعلیم پر ہر درجہ کا آدمی عمل کرسکتاہے میں نے اوپر ذکر کیاتھا کہ تیسری خوبی جس کامکمل تعلیم میں پایاجاناضروری ہے یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا سب انسانوں کے لئے ممکن ہو.یہ خوبی بھی مذکورہ بالا تعلیم میں پائی جاتی ہے.جہاں یہ تعلیم نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے وہاں اس پر عمل بھی ہردرجہ اورطبقہ کے آدمیوں کے لئے ممکن ہے.وہ نہ توادنیٰ اخلاق کی تعلیم دے کر خاموش ہوجاتی ہے کہ اعلیٰ ترقیا ت کے خواہش مند اس سے تسلی نہ پا سکیں اورنہ اعلیٰ اخلاق کے بیان پر بس کردیتی ہے کہ کمزورانسا ن نیکی سے محروم رہ جائیں.بلکہ وہ نیکی اوربدی کے تمام مدارج کو
Page 176
بیان کرتی ہے تاکہ بدوںکو بدی چھڑانے میں مدد دے اورنیکوں کی نیکی کے حصول میں اعانت کرے.ایک بدی میں ڈو بے ہوئے انسان کو یہ کہنا کہ توایسانیک ہوجا کہ سب دنیا کاسہاراتوہی ہو اورتوسب کے لئے بمنزلہ ماں کے ہوجا.ایسا ہی بے فائدہ ہوگا جیسے ایک الف،ب پڑھنے والے کوایم.اے کاکورس شروع کرادینا.اسی طرح ایک اعلیٰ درجہ کے نیک آدمی کویہ کہنا کہ دیکھو بغاوت اورسرکشی نہ کرو اورظلم نہ کروبالکل فضول بات ہوگی.جو شرارت میں بڑھاہواہواس سے پہلے بڑی بدیا ں چھڑوائی جائیں تبھی اصلاح ممکن ہے.اورجو نیکی میں ترقی کررہاہو اسے صرف باریک گناہوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کرنا کو ئی فائدہ نہیں دے سکتا.کیونکہ بد ی کی عام راہوں کوتووہ پہلے ہی چھوڑ چکا ہے.اوریہ سب خوبیاں اوپر کی تعلیم میں موجود ہیں.وہ بڑی نیکی کی راہیں بھی بتاتی ہے اورچھوٹی نیکی کی بھی.اوربڑی بدیوں سے بھی بچاتی ہے اورچھوٹیوں سے بھی.اورہر شخص خواہ کسی درجہ کاہواس کو سمجھ سکتاہے اوراس پر عمل بھی کرسکتاہے.ہر چیز کی تکمیل کے چھ درجے ہوتے ہیں اور ساتواں کمال کا یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں تین درجے بدی کے اورتین درجے نیکی کے بیان فرمائے گئے ہیں.چونکہ نیچر میں ہمیں یہ قانون رائج معلوم ہوتاہے کہ تکمیل سے پہلے ہرشے کو چھ مدارج طے کرنے پڑتے ہیں.اس آیت میں گویا روحانی تکمیل کاسب نصاب بیان کردیاگیا ہے جسے پڑھ کر انسان ساتواں درجہ یعنی کمال کا مقام حاصل کرسکتاہے.بدی سے نیکی کی طرف آنے کے مدارج جوبدیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں انہیں پہلی جدوجہد بغی سے بچنے کے لئے کرنی پڑتی ہے.اس دلدل سے نکلتاہے تومنکر کاکیچڑ آجاتاہے اورجب منکر کے کیچڑ سے نکلتاہے توفحشاء کے گردوغبارمیں پھنس جاتا ہے.جب اس سے نجات پاتاہے تو عدل کے مرغزارکی حدشروع ہوجاتی ہے.اسے قطع کرلیتا ہے تواحسان کاچمن آجاتاہے.اسے طے کرلیتا ہے توایتا ء ذی القربیٰ کاچشموں والا باغ آجاتاہے اوراس کے آگے جنت ہی جنت ہے.اسی مناسبت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے (کنز العمال باب الثامن فی بر الوالدین.الأم).اس آیت میں بھی ایتاء ذی القربیٰ کو جوماں کے سے سلوک پردلالت کرتا ہے تکمیل کاآخری اورجنت سے پہلا مقام بتایاگیاہے.اورجنت کا مقام ذا کر کا ہے جو خدا تعالیٰ میں محو ہوجاتا ہے اورخدا تعالیٰ اس کے دل میں ڈیراجمالیتا ہے اورمحب اورمحبوب دائمی اورنہ ٹوٹنے والے رشتہ میں پروئے جاتے ہیں.اس آیت کی اہمیت ابتداء اسلام سے ہی مسلّم ہے یہ آیت ہرجمعہ میں خطبہ کے دوسرے حصہ میں پڑھی
Page 177
جاتی ہے اوریہ رواج حضر ت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ کے عمل سے شروع ہواہے (تاریخ الخلفاء ذکر عمر بن عبد العزیز).اس امرسے ظاہر ہے کہ مسلمان ابتداہی سے ا س آیت کی اہمیت کو سمجھتے رہے ہیں.عیسائی اس آیت پر بہت چڑتے ہیں اورویری نے تویہاںتک لکھ دیا ہے کہ مسلمان اس تعلیم کو اعلیٰ اعلیٰ کہہ کرپیش کرتے ہیں(تفسیر القرآن از وہیری) وہ ہمارے مسیح کی تعلیم سے تواس کامقابلہ کریں جو متی باب۲۲.۳۷.۳۹میں بیان ہے جہاں لکھا ہے ’’خداوند اپنے خدا سے سارے دل اوراپنی ساری جان اوراپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑااورپہلاحکم یہی ہے اوردوسرااس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابرمحبت رکھ.‘‘حالانکہ مسیح کی اس تعلیم پر عیسائیوں کافخر بالکل بے جااورفضول ہے.قرآن مجید کی تعلیم کے مقابلہ میں اس تعلیم کو پہلے قد م کی سی حیثیت حاصل ہے.عیسائیت کی تعلیم کا مقابلہ اسلامی تعلیم سے بے شک مسیح نے کہا کہ ’’خدا سے اپنے سارے دل اورساری جان اورساری عقل سے محبت رکھ‘‘.مگرسوال یہ ہے کہ دل کس نے دیا ؟جان کس نے دی ؟عقل کس نے عطافرمائی ؟ اللہ نے.پس ان کے ساتھ جو بھی محبت کی جائے گی.وہ عدل کے مقام سے اوپر نہیں جاسکتی ہاں عدل کالفظ اس فقرہ سے بہت زیادہ وسیع ہے کیونکہ ان چیز وں کے علاوہ اوربھی چیزیں ہیں جن کی قربانی ضروری ہوتی ہے مثلاً احساسات و جذبات.جب تک انسان اپنی ہر ایک خواہش ہرایک ارادہ اوردنیا کی ہرچیز سے بڑھ کر خدا سے محبت نہ کرے گاتووہ عدل کرنے والا نہیں کہلاسکتا.بے شک ساری جان سے محبت کرنا اچھی بات ہے مگر کئی لو گ ہیں جو اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور کئی ایسی طبائع ہیں جو اپنے دل اوراپنی جان کی نسبت مال سے زیادہ پیا رکرتے ہیں.اور کئی اس فطرت کے ہوتے ہیں جواپنی عزت و ناموس کی خاطراپنی جان تک قربا ن کردینے سے دریغ نہیں کرتے.توخالی ساری جان ،سارے دل اورساری عقل کے لفظ کے اند ر ہرقسم کی قربانی اورخدا تعالیٰ سے کامل محبت جس کو عدل کالفظ ظاہرکرتاہے نہیں آسکتی.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ مختلف قسم کے جذبا ت کویوں بیان فرمایا ہے قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ا۟قْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ١ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ( التوبۃ :۲۴)کہہ دے کہ اگرتمہیں اپنے آباؤاجداد یااپنی اولاد یااپنے بھائی یااپنی بیویاں یااپنی قوم اورقبیلہ یااپنے اموال اورتجارتیں خدااوراس کے رسول سے اوراس کی راہ میں جہادسے پیارے ہیں توتم وہ چیز نہیں ہوجوقبول کئے جانے کے لائق ہوپس انتظارکرو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کافیصلہ آجائے.اللہ تعالیٰ فاسق قوم کوکبھی کامیاب نہیں کرتا.
Page 178
فطرت انسانی کی محبوب ترین اشیاء کی تفصیل دیکھو اس میں ہرقسم کے انسانوں کے لئے خدا تعالیٰ سے محبت کامعیار بتادیاہے.بعض لوگ جن میںاحسان کی قدر کامادہ زیادہ ہوتاہے انہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے.قرآن مجید نے ان لوگوں کے لئے فرمایاکہ قُلْ اِنْ کَانَ اٰبَآؤُکُمْ اگرتم خداکے مقابلہ میں اپنے آباء سے زیادہ محبت کرتے ہو توتم ابھی تک مومن نہیں.بعض لوگوں کے اندر بقائے نسل کاتقاضابہت نمایاں ہوتا ہے اوروہ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ پیا رکرتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ’’ابناء کم ‘‘ کالفظ فرماکر اس طرف اشار ہ فرمایا کہ جب تک تم اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر خدا سے محبت نہ کروگے اس وقت تک تمہاراایمان قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا.پھر کئی لوگوں کو جتھا سب سے پیارالگتاہے.ایسے لوگوں کے لئے’’اِخْوَانُكُمْ‘‘کالفظ رکھ کر فرمایاکہ جب تک تم اپنے بھائیوںسے بھی زیادہ خدا تعالیٰ سے محبت نہ کروتم اللہ تعالیٰ کاقرب حاصل نہیں کرسکتے.کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر شہوت کاغلبہ ہوتاہے.اورانہیں اپنی بیویاں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں.ایسے لوگوں کے لئے ’’اَزْوَاجُكُمْ‘‘کالفظ رکھا گیا اوربتایاگیا کہ اس صورت میں جب تک تم اپنی بیویوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع نہ کروگے تم اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل نہیں کرسکتے.بعض لوگ اپنے قبیلے اورخاندان کو سب چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں ان کے لئے ’’عَشِيْرَتُكُمْ‘‘کالفظ فرماکرتوجہ دلائی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے قبیلہ سے بھی زیادہ نہ چاہوگے اللہ تعالیٰ کاقرب حاصل نہیں کرسکتے.بعض ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ جنہیں روپیہ اپنی اولاد اورجان سے زیادہ عزیزہوتاہے.بیسیوں ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں جنہوں نے باوجود مالدارہونے کے اپنی اولاد کے لئے کوئی دوائی تک منگاکرنہ دی اورو ہ ان کے سامنے تڑپ تڑپ کرمرگئی توایسے لوگوں کے لئے فرمایاکہ اپنے اموال کو بھی خدا تعالیٰ کی محبت پر مقدم نہ رکھو ورنہ کبھی نیکی کا اعلیٰ مقام نہ پاسکو گے.بعض لوگ اس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ و ہ اپنے ملک اوروطن کی خدمت کو اپنی ہرایک چیز پر مقدم سمجھتے ہیں اوران کانعرہ ہی حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِیْمَانِ ہواکرتاہے.جیساکہ ہمارے ملک میں ہجرت کے زمانہ میں ہزاروں لوگ اپنی اولاد،جائداد اوراموال چھوڑ کر ملک کی محبت کے نام پر ملک بدر ہوگئے.ایسے لوگوں کے لئے فرمایاکہ اگرتمہیں اپنے وطن اورگھر خدا سے زیادہ پیارے ہیں توتم ابھی مومن نہیں ہو.قرآن کریم نے عد ل کی یہ مختصرسی تشریح فرمائی ہے اب اس تعریف کے مقابلہ میں ’’سارے دل ساری عقل
Page 179
اورساری جان‘‘والی بات کیا حقیقت رکھتی ہے ؟ متی کے اس حکم کادوسراحصہ یہ ہے.’’دوسرااس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ.‘‘اول تویہی خلاف عقل ہے کہ اس حکم کو پہلے کی مانند قرار دیاجائے بے شک یہ ضروری حکم ہے مگر اسے پہلے حکم کی مانند قرار نہیں دیاجاسکتا.خدا تعالیٰ بہرحال مقدم ہے.مانند ماننے کاتویہ مطلب ہے کہ اگر کبھی خدا تعالیٰ کاحکم اورپڑوسی کی خواہش ٹکراجائیں توہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اورکہیں کہ یہ دونوں پہلو برابر ہیں یہ بھی ویساہی پیاراہے اوروہ بھی.ایک کودوسرے پر کس طرح ترجیح دی جائے.عیسائیت کی تعلیم کا معیار صفت عدل سے بڑھ کر نہیں اورپھر یہ حکم بھی عدل سے اوپر نہیں جاتا.کیونکہ اس میں ہرشخص کو یہ حکم دیاگیا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی محبت کرے.توگویایہ وہ پہلا مقام ہے جس کواسلام نے عدل قرار دیا ہے یازیادہ سے زیادہ احسان کا مقام ہے مگر اسلام اس مقام سے انسان کو اوپر لے جاتاہے اورفرماتا ہے کہ نہ صرف تم عدل کرو اورنہ صرف احسان کرو بلکہ تم بنی نوع انسان سے ایسا سلوک کرو جس میں کسی قسم کی ریاء یابدلے کی خواہش کاشائبہ بھی نہ ہو.جس طرح ماں اپنے بچہ سے محبت کرتی ہے وہ اُسے اپنے برابرنہیں چاہتی بلکہ اپنے آپ کو اس کے آرام کے لئے قربان کردیتی ہے.اس کے علاوہ قرآن کریم نے اس آیت میں نیکی اوربدی کے جومدارج بیان فرمائے ہیں اورپھر جو ان کی ترتیب بیان فرما کر ان سے بچنے کی راہنمائی کی ہے وہ انجیل میں کہا ں؟پھر قرآن مجید نے اس حکم میں مختلف فطرتوں کالحاظ رکھتے ہوئے ایک جامع تعلیم دی ہے.مگرانجیل میں ان سب باتوں کو نظرانداز کردیاگیاہے.پس قرآن کریم کی تعلیم ہی جامع.کامل.قابل عمل اوراعلیٰ ہے.وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَ لَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ اور(چاہیے کہ )اللہ(تعالیٰ)کے (ساتھ کئے ہوئے اپنے )عہد کو جب تم نے (اس سے کو ئی )عہد کیا ہوپوراکر و بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا١ؕ اِنَّ اورقسمو ںکوانہیں پختہ کرنے کے بعد جبکہ تم نے اللہ(تعالیٰ)کو (اس کی قسم کھا کر )اپنا ضامن بنالیا ہے مت
Page 180
اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ۰۰۹۲ توڑو.جوکچھ تم کرتے ہو اللہ(تعالیٰ اُسے )یقینا جانتاہے.حلّ لُغَات.کَفِیْلٌ: کَفَلَ الرَّجُلَ والصَّغِیرَ (کَفْلًا وَکَفَالَۃً)عَالَہٗ وَاَنْفَقَ عَلَیْہِ وَقَامَ بِہٖ.کسی کی پرورش کی اوراس کے اخراجات کواٹھایا.اس سے اسم فاعل کَافِلٌ ہے.کَفَلَ بِالْمَالِ (کَفْلًا وَکُفُوْلًا)ضَمِنَہٗ.کسی مال کاضامن ہو ا.اوراس سے صیغہ صفت کَفِیْلٌ آتاہے کفیل کے معنے ضامن کے ہیں.کَافِلٌ اورکَفِیْلٌ ایک ہی معنے رکھتے ہیں.نیز لفظ کَفِیْلٌ مذکرومؤنث دونوںکے لئے استعمال ہوتاہے کہتے ہیں رَجُلٌ کَفِیْلٌ.وَامْرَاَۃٌ کَفِیْلٌ.اورلیثؔنے کَفِیْلٌ اورکَافِلٌ کے درمیان فرق کیا ہے.کہتاہےکہ کَفِیْلٌ ضامن کو کہتے ہیں اورکَافِلٌ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کے اخراجات برداشت کرتاہے.(اقرب) تفسیر.عہد اللہ کی تشریح بِعَهْدِ اللّٰهِ.عہداللہ سے کیا مراد ہے.اس کی تشریح دوسری جگہ قرآن شریف میں آئی ہے (۱)اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.’’اِنَّ الَّذِیْنَ یُبَایِعُوْنَکَ اِنَّمَایُبَایِعُوْنَ اللّٰہَ یَدُاللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیْھِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَاِنَّمَایَنْکُثُ عَلیٰ نَفْسِہٖ وَمَنْ اَوْفٰی بِمَاعَاھَدَ عَلَیْہُ اللّٰہَ فَسَیُؤْتِیْہِ اَجْرًاعَظِیْمًا ‘‘ (الفتح :۱۱) وہ لوگ جوتیری بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ کی بیعت کرتے ہیں اوراللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے.پھر جو شخص اس بیعت کوتوڑ دیتاہے وہ اپنے نفس کانقصان کرتاہے اورجواس ’عہداللہ‘ کوپوراکرتاہے تواس کو خدا تعالیٰ اجرعظیم دے گا.عہد اللہ سے مراد اسلام قبول کرنا ہے اس آیت سے معلو م ہواکہ ’’عہداللہ ‘‘ سے مراد اسلام ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیعت مراد ہوتی تھی اورآپ کے بعد اسلام میں داخل ہونا.(۲)اللہ تعالیٰ کفار کاقول نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے وَقَالَتْ طَّآئِفَۃٌ مِّنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِیْ اُنْزِلَ الآیہ(ال عمران:۷۳).کہ کفار کہاکرتے تھے کہ تم صبح کے وقت مسلمان بن جائو اورشام کو مرتد ہوجانا.اسی تسلسل کے ضمن میں چند آیات کے بعد فرماتا ہے بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ اَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓىِٕكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَ لَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ١۪ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ(اٰل عمران:۷۷.۷۸)یوں نہیں جو تم کہتے ہو بلکہ بات یوں ہے کہ جواپنے عہد کوپوراکرے اورتقویٰ سے کام لے تو(اس کاانجام اچھا ہوگا کیونکہ)اللہ متقیوں سے پیارکرتاہے.جولوگ اللہ تعالیٰ
Page 181
کے عہد اوراپنی قسموں کے بدلہ میں دنیوی فوائد اٹھاتے ہیں یقیناًان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگااور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہ کرے گااورنہ قیامت کے دن ان کی طرف(محبت سے)دیکھے گا.اورنہ انہیں پاک قرار دے گااورانہیں دردناک عذا ب ملے گا.ان آیات سے بھی ظاہر ہے کہ ’’عہداللہ‘‘سے مراداسلام قبول کرناہے.(۳)پھر فرمایا ہے وَ لَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ١ؕ وَ كَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا (الاحزاب: ۱۶).فرمایا کہ ان لوگوں نے لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ کاعہد کیا تھا مگراسے پورانہ کیا.اوراللہ تعالیٰ سے جوعہد کئے جاتے ہیں ان کے توڑنے پرضرورپرسش ہوتی ہے.لیکن جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے کہ ان کا یہ عہد کہا ں مذکور ہے تومنافقوں کی طرف سے اس کا ذکر قرآ ن کریم میں کہیں نہیں ملتا.ہاں اللہ تعالیٰ کاحکم ملتاہے.چنانچہ سورۃ انفال میں ہےيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ(الانفال :۱۶)کہ اے مومنو! جب کفار سے تمہارامقابلہ ایسی حالت میں ہو کہ تم مل کر حملہ کرنے لگے ہوتوکبھی پیٹھ نہ پھیراکرو.یہ اللہ تعالیٰ کااپنا حکم ہے منافقوں کاکوئی ایساعہد قرآن وحدیث میں مذکورنہیں.آنحضرت ؐ کے زمانہ میں عہد اللہ سے مراد بیعت والا عہد تھا پس معلو م ہواکہ ’’عہداللہ‘‘سے مراد وہی بیعت والاعہد تھا جس میں سب نیک باتوں کے ماننے کاعہد کیا گیا تھا.اورسب احکام الٰہی اس میں شامل تھے.چنانچہ سور ۃ توبہ میں ا س عہد کی تشریح یوں کی گئی ہے اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ١ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ١۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ١ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا۠ بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ١ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.(التوبۃ :۱۱۱)کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اوران کے اموال اس وعد ہ کے مقابل کہ انہیں جنت ملے گی خرید لئے ہیں.چنانچہ اس سودے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں کبھی تو وہ دشمن کو قتل کردیتے ہیں کبھی خود مارے جاتے ہیں.یہ جنت دینے کاوعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکا وعد ہ ہے جوتورات وانجیل اورقرآن سب میں بیان ہواہے.اورجو اللہ تعالیٰ سے عہد کرکے اسے پوراکرتے ہوں ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس نفع مند بیع پر جو تم نے کی ہے خوش ہوجائو اوریہ بیع ایک بہت بڑی کامیابی ہے.غرض قرآن مجید سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ’’عہداللہ ‘‘سے مراد اسلام ہی ہے اوراِذَاعَاھَدْ تُّمْ کے معنے یہی ہیں کہ جب تم مسلمان ہوئے ہو تواسلام کی تعلیم پرپورے طورسے عمل کرو.چونکہ اسلام کی تعلیم کاخلاصہ اِنَّ اللّٰہَ
Page 182
یَاْمُرُ والی آیت میں بتایاگیاتھا اس لئے اس کے بیان کرنے کے بعد اس آیت میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اب تم لوگ اس تعلیم کے مطابق عملدرآمد کرو.اس آیت کے پہلے حصہ میں یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تم جو عہد کرتے ہو اس کو بھی پوراکرو.اورجوتمہارے آپس میں معاہدات ہوتے ہیں ان کو بھی مت توڑو.یعنی جب تم خدا تعالیٰ کوضامن کرکے کسی انسان سے معاہد ہ کروتوا س کو ضرو ر پوراکرو.کیونکہ تم خدا تعالیٰ کو ضامن مقررکرچکے ہو.پس خدا کانام لے کر کئے ہوئے معاہد ہ کو اگر تم توڑوگے توگویا خدا تعالیٰ کو بدنام کرنے والے بنوگے.اورخدا تعالیٰ کوغیرت آئے گی اوراسے تمہیں سزادینی پڑے گی.اس آیت میں پھر اسی مضمون کوقائم رکھا گیا ہے جو پہلی آیت میں بیان ہواتھا.یعنی حقوق اللہ اورحقوق العباد دونوں کوپوراکرنے کا حکم دیاگیاہے.گویااسلام اورعہدالٰہی اللہ تعالیٰ اوربندوں کے صحیح تعلق پیداکرنے کے دونام ہیں.حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کا حکم یہاں جویہ فرمایا کہ اس عہد کو پوراکرو جس میں تم نے اللہ تعالیٰ کو ضامن مقرر کیاہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے عہد پورے نہ کرو توکوئی حرج نہیں.کیونکہ خدائی عہد میں سچ بولنا شامل ہے.بلکہ ان الفاظ سے اس مضمون کی طرف اشارہ کیاہے کہ انہی عہدوں کی پابندی انسان پر فرض ہے کہ جن کاضامن اللہ تعالیٰ ہو.جن عہدوں کاضامن اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کاپوراکرنا غیرضروری ہی نہیں بلکہ گناہ ہے.مطلب یہ کہ ہروہ عہدجو انصاف اورسچائی پر مبنی ہو اس کا اللہ تعالیٰ ضامن ہوتاہے.کیونکہ وہ ہرمومن سے سچائی کاعہد لے چکا ہے اورجو شخص اس عہد کے بعد کسی انسان سے کسی جائزامرکااقرار کرتا ہے وہ اس عہد کے ساتھ گویا خدا تعالیٰ سے بھی ایک عہد باندھتاہے اورخدا تعالیٰ ا س عہد کاضامن ہو جاتا ہے.لیکن جو عہد کسی ناپاک امریاظلم کے متعلق ہو ا س کاپوراکرناضرور ی نہیں بلکہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس عہد کا ضامن نہیں کیونکہ وہ گناہ اورناپاکی کے لئے ضامن نہیں ہوتا.غرض اللہ تعالیٰ کے ضامن ہونے سے اس طرف اشارہ نہیں کیا کہ جن عہدوں پرقسم کھائو صرف انہیں پوراکرو.بلکہ اس مضمون کی طرف اشار ہ کیا ہے کہ سب وہ عہد جو عدل ،احسان اورایتاء ذی القربیٰ کے مطابق ہوں انہیں پوراکرو اوروہ عہد جن میں فحشاء ،منکر اوربغی کارنگ پایا جاتاہوانہیں پورانہ کرو.ان کے بارہ میں تم سے کوئی سوال نہ ہوگا.کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کاضامن نہیں.بلکہ اُن سے منع کرتا ہے.مذکورہ بالا حکم میں ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو اگر کسی ناجائز امر پرقسم کھا لیتے ہیں توعہد کی پابندی کے نام سے اس پر مصر رہتے ہیں.
Page 183
وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا١ؕ اور تم اس ڈر سے کہ کوئی قوم ایسی(نہ)ہوجائے جو (کسی)دوسری قوم سے زیادہ طاقتورہو اپنی قسموں کو آپس میں تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ دھوکا کرنے کا ذریعہ بناتے ہوئے اس عورت کی طرح مت بنو جس نے اپنا(محنت سے کاتاہوا)سوت (اس کے) اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ١ؕ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ١ؕ وَ لَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ مضبوط ہوچکنے کے بعد توڑ کر پارہ پارہ کردیاتھا اس (ذریعہ )سے اللہ (تعالیٰ عنقریب)تمہاراامتحان لے يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ۰۰۹۳ گااورجس با ت کے متعلق تم آپس میں اختلاف کرتے رہے ہوگے اس (کی حقیقت )کووہ قیامت کے دن ضرور تمہارے سامنے کھول(کر رکھ )دے گا.حلّ لُغَات.نَقَضَتْ نَقَضَتْ نَقَضَ سے مؤنث کاصیغہ ہے.اورنَقَضَ الْبِنَاءَ کے معنے ہیں.ھَدَمَہٗ.عمارت کو گرادیا.نَقَضَ الْعَظْمَ:کَسَرَہُ.ہڈی کو توڑ دیا.نَقَضَ الْحَبْلَ:حَلَّہُ.رسہ کے بل کو کھول دیا.(اقرب) غَزْلَھَا: غَزَلَتِ الْمَرْأَۃُ الْقُطْنَ وَالصُّوْفَ: مدَّتْہُ وَفَتَلَتْہُ خِیْطَانًا.عورت نے سُوت کاتا.اَلْغَزْلُ مصدر ہے.اورغزل سُوت کوبھی کہتے ہیں.(اقرب) انکاث اَنْکَاثٌ نِکْثٌ کی جمع ہے.اَلنِّکْثُکے معنے ہیں مَانُقِضَ مِنَ الْاَکْسِیَۃِ وَالْاَخْبِیَۃِ لِیُغْزَلَ ثَانِیَۃً کچے تاگے.اس کی جمع اَنْکَاثٌ آتی ہے.(اقرب) دَخَلًا الدَّخَلُ کے معنے ہیں مَادَاخِلُکَ مِنْ فَسَادٍ فِی الْعَقْلِ اَوْ فِی الْجِسْمِ.جسم اورعقل میںخرابی.اَلْـخَدِیْعَۃُ وَالْمَکْرُ.دھوکااورفریب اورآیتلَا تَتَّخِذُوْۤا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ میں انہی معنوں میں آیاہے اوروہاں پر مفعول لہٗ ہے.(اقرب) اَرْبٰی اَرْبٰی رَبَی سے اسم تفضیل ہے اوررَبَا(یَرْبُو)الْمَالَ کے معنے ہیں زَادَوَنَمَا.مال زیادہ ہوگیااوربڑھ
Page 184
گیا.اَرْبَی عَلَیْہِ کَذَا.یعنی کسی سے آگے بڑھ گیا(اقرب)پس اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ کے معنے ہوں گے کہ ایک قوم دوسری سے زیاد ہ طاقتورہے.یَبْلُوْکُمْ.یَبْلُوْ بَلَی سے مضارع واحد مذکر غائب کاصیغہ ہے اوربَلَاہُ یَبْلُوْہُ بَلَاءً کے معنے ہیں.جَرَّبَہُ وَاخْتَبَرَہُ.اس کاامتحان لیا (اقرب)پس یَبْلُوْکُمْ کے معنے ہوں گے کہ وہ تمہاراامتحان کرتا ہے.تفسیر.اس آیت کا مطلب پہلی آیت سے متعلق ہونے کی صورت میں اس آیت کو ایک نیامضمون بھی قرار دیاجاسکتاہے اورپچھلی آیت کے مضمون کا تسلسل بھی قراردیاجاسکتاہے.اگر پہلی آیت کے مضمون کوہی جاری سمجھا جائے تواس کے معنے یہ ہوں گے کہ آپس کے معاہدات کوپوری طر ح سے نبھائو.اگر تم ان عہدوں کوتوڑو گے تو خدا تعالیٰ نے جوتمہاری مضبو ط جماعت بنادی ہے وہ تباہ ہوجائے گی اورآپس کااعتبار جاتا رہے گا.معاہدات کی پابندی قومی اتحاد کے قیام کے لئے اشد ضروری ہوتی ہے.کیونکہ جماعت کاقیام ایک دوسرے سے حسن سلوک پر مبنی ہوتاہے.اورحسن سلوک اس وقت تک رہتا ہے جب تک لوگ معاہدات کی پابند ی کریں.جب لو گ معاہدات پو رے نہ کریں.توپہلے بددلی اوراس کے بعد بد ظنی پیداہوجاتی ہے اورایک شخص کے برے عمل کے نتیجہ میں دوسرے سینکڑوں آدمی قومی نظام کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں.پس چاہیے کہ انسان جس طر ح بھی ہوسکے اپنے وعدوں کو پوراکرے تاکہ اعتبارقائم ہو اورلوگ برضاورغبت ایک دوسرے کی امداد کے لئے تیار ہوں اورقوم ترقی کرسکے.قومی عہد کی تشریح انفرادی عہدکے علاوہ ایک قومی عہد بھی ہوتاہے یعنی افراد ایک شخص کے ہاتھ پر قومی ترقی کے لئے عہد کرتے ہیں جس کانام خلافت ہے.وہ عہد بھی اس کے اندر شامل ہے اوراس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے.فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری ایک جماعت بنادی ہے اورایک نظام قائم کردیا ہے.اور تم نے ا س نظام کی پابندی کی قسمیں کھائی ہیں.اب اس کی پابندی کرتے رہنا.ورنہ نتیجہ یہ ہوگاکہ تمہاری قربانیوں سے جورعب اسلام کاقائم ہواہے وہ جاتارہے گا.اورپھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی.یہ ایک بہت بڑاسیاسی نکتہ بتایاہے چند آدمیوں کے تفرقہ سے سب نظام برباد ہو جاتا ہے اورقوم کی محنت اکارت جاتی ہے اورنئے سرے سے محنت اورقربانی کی ضرورت پیش آتی ہے.مگر اُدھڑی ہو ئی چیزپھر اس طرح نہیں جڑتی جیسے کہ نئی اورپھٹے ہوئے دل پھر ا س طرح نہیں ملتے جس طرح کہ وہ جوہمیشہ متصل رہے.اس لئے اس عہد کے قیام کے لئے نہایت سخت کوشش کی ضرورت ہوتی ہے.
Page 185
دوسری اقوام سے بھی معا ہدات کی پابندی لازمی ہے ا س آیت کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ اس میں غیر قوموں کے ساتھ معاہدات کا بھی ذکر ہے.اس مضمون کے لحاظ سے اس آیت کو ایک مستقل مضمون قراردینا ہوگا.یعنی لَاتَکُوْنُوْاسے نیامضمون شروع سمجھا جائے گا.اورمطلب یہ ہو گا کہ جس طر ح اللہ تعالیٰ کے عہد اوراپنے اندرونی عہد کی پابند ی لازمی ہے.اسی طرح دوسری اقوام کے ساتھ جو عہدکئے گئے ہوں ان کی پابند ی بھی ضروری ہے.ان معاہدات کی نگہداشت رکھو ورنہ دنیا کاامن برباد ہوجائے گا.چنانچہ دَخَلًا کا لفظ بھی اسی بات کو ظاہر کرتا ہے اور کَالَّتِیْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ٍ سے بھی یہی مراد ہے کہ امن کے قائم ہونے کے بعد فساد کی صورت پیدانہ کرو.اس صورت میں اس آیت کے تین معنے ہوسکتے ہیں.دوسری قوم سے معاہدہ کرتے وقت صفائی نیت ضروری ہے (۱)یہ جائز نہیں کہ تم کسی دوسری قوم سے اس لئے صلح کرلو کہ ابھی وہ طاقتور ہے تم اس کامقابلہ نہیں کرسکتے.معاہدہ کے بعد جب وہ تمہاری طرف سے غافل ہوجائے گی توتم اند رہی اندر تیاری کرکے ایک د ن اس پر حملہ کرکے اسے تباہ کردوگے.سیاسی دنیا ا س قسم کی حرکات ہمیشہ سے کرتی آئی ہے.اسلام کی بنیاد چونکہ عدل،احسان اورایتاء ذی القربیٰ پرہے وہ اس فعل کو خواہ وہ دشمن اسلام کے مقابل پر کیا جائے ناپسند کرتااوراس سے منع فرماتا ہے.ایسے معاہدے ناجائز ہیں جو کسی قوم کو کمزور کر کے اس کے ملک پر قبضہ کرنے کی نیت سے ہوں (۲)دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ ایسے معاہدات نہیں کرنے چاہئیں کہ جن کی غرض یہ ہو کہ کسی کمزورقوم کے ساتھ بظاہر تومعاہدہ کیا جائے اوردراصل غرض اس کے ملک پر قبضہ کرنے کی ہو.جیسا کہ یورپین قومیں آج کل کررہی ہیں.(۳)تیسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ ایسے معاہدات ہرگز جائز نہیں جن کی غرض معاہد قوم کو کمزورکرناہو.چاہیے کہ جس سے صلح کرو اس سے پوری صلح کرو.اس آیت میں کس قدر زبردست اخلاقی تعلیم دی ہے اوربتایا ہے کہ قومی برتری بے شک اچھی چیز ہے لیکن دھوکے اورفریب سے اس کاحصو ل ہرگز جائز نہیں.معاہدات کی غرض قیام امن ہوناچاہیےنہ کہ دوسرے کا نقصان یا فریب دہی.آج کل یورپ کی تباہ شدہ حالت معاہدہ کی اسلامی تعلیم کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے مقابل
Page 186
میں دیکھو یورپ آج کیا کررہا ہے.معاہدات کرکے کمزورقوموں کو تباہ کیا جاتا ہے.جیسے چین میں ہوا.مصر میں ہوا.ترکی میں ہوااورایران میں ہوا.اورایک زمانہ میں ہندوستان میں بھی ہوچکا ہے.اورآج کل پھر پولینڈ.فرانس.فن لینڈ.ناروے.رومانیہ.چیکوسلواکیہ وغیرہ ممالک سے ایسے ہی واقعات پیش آرہے ہیں.معاہد ہ کے متعلق مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوںکو حکم دیا ہے کہ :.(۱)کوئی معاہد ہ اس نیت سے نہ کیا جائے جس کامقصد کسی دوسری طاقت کودھوکا دے کرکمزورکرنا ہو.(۲)کسی کمزورقوم سے کو ئی ایسا معاہدہ نہ کیاجائے جس کامقصد یہ ہو کہ اس قوم کو اس معاہدہ کے پیچ میں لاکر اپنے ماتحت کرلیا جائے.(۳)کوئی معاہد ہ اس نیت سے نہ کیاجائے جس کامقصد کسی دوسری طاقت کو ترقی سے روکنا ہو.قیام امن کے لئے کیا ہی لطیف تعلیم دی ہے.اگر اس کی پابندی کی جائے توتما م فسادات یکدم مٹ سکتے ہیں.اتحادیوں اور ائتلافیوںکی سابق عالمگیراورموجودہ لڑائی ایسے ہی معاہدات کے نتیجہ میں پیداہوئی اورہورہی ہے.معاہدہ وارسائی نہ ہوتا تویہ نئی جنگ بھی نہ ہوتی قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایسے معاہدات جائز ہی نہیں.معاہد ہ نیک نیتی پر مبنی ہوناچاہیے اوراس کاواحد مقصد قیام امن ہوناچاہیے.اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ میں اللہ تعالیٰ نے بتایاہے کہ اے مسلمانو!یہ مواقع بطورامتحان آتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گاکہ تم طاقت پا کر اسلام کی اخلاقی تعلیم پر کس طرح کاربند رہتے ہو اوردنیا کی ترقیات تمہیں کہیں دوسری اقوام کے نقش قدم پر تونہیں چلادیتیں.کس مپرسی کی حالت میں اسلام کی یہ اعلیٰ تعلیم اس کی صداقت کی دلیل ہے یہ مضمون قرآن مجید کی سچائی کاکتنا بڑاثبوت ہے اوراسلام کی برتری کی کیسی عظیم الشان دلیل ہے.ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تشریف رکھتے ہیں اورمسلمان ایک چپہ بھر زمین کے بھی مالک نہیں.مگر اس شان اورعظمت کے ساتھ ایک زبردست حکومت کے احکا م بیان ہورہے ہیں.اورپھر ایسے رنگ میں کہ ہرعقلمند اورشریف انسان انہیں سن کر اس تعلیم کی برتری کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا.کیایہ سچ نہیں کہ آ ج بھی جبکہ تیرہ سوسال گذر چکے ہیں اس کلام کی سچائی ظاہرہورہی ہے.آج کل کے فسادات اورقوموں کی بے چینیا ں صرف ان احکام کو نظر انداز کردینے کی وجہ سے ہی پیداہورہی ہیں.
Page 187
وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لٰكِنْ يُّضِلُّ اوراگراللہ (تعالیٰ)اپنی (ہی )مشیت نافذ کرتا تووہ تم(سب)کو ایک ہی جماعت بناتا.لیکن(وہ ایسانہیں مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ١ؕ وَ لَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ کرتا.بلکہ)جوشخص (گمراہی کو)چاہتاہے اسے وہ گمراہ کرتا ہے اورجو (ہدایت کو )چاہتاہے اسے وہ ہدایت دیتا تَعْمَلُوْنَ۰۰۹۴ ہے اورجوکچھ تم کیاکرتے ہو ا س کی بابت (قیامت کے دن ) تم سے پوچھا جائے گا.تفسیر.اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو جبراً جاری نہ کرنے کی وجہ یہاں سوال ہوسکتاتھاکہ تعلیم تویہ بہت اعلیٰ ہے مگراللہ تعالیٰ نے ا س تعلیم کو جبراً کیوں نہ جاری کردیا کہ فسادات سے دنیا محفوظ ہوجاتی.اس بارہ میں فرماتا ہے کہ بے شک اگراللہ تعالیٰ اپنی مشیت جاری کرتا توایسا ہی کرتا.لیکن چونکہ انسان کومقدرت دے کر اس کاامتحان لینامقصود ہے اس لئے جو گمراہ ہوناچاہتاہے خدا تعالیٰ اسے گمراہ ہونےدیتاہے.اورجو مومن بنناچاہتاہے اس کی راہنمائی ایمان کی طرف کرتا ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے اعما ل کا جواب دہ بنایا ہے.اوریہ امر جائز نہیں جب تک اسے قدرت دے کر آزادنہ چھوڑدیاگیاہو.تاوہ اپنی مرضی سے ہدایت کایاگمراہی کا جوراستہ بھی پسند کرے اختیارکرلے.اس آیت میں مسلمانوں کو نصیحت اس آیت میں مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی ہے کہ ممکن ہے تمہارے دل میں یہ خیال پیداہوکہ ہم ایسے معاہدات اسلام کے فائدہ کے لئے کریں گے پھر وہ کیوں ناجائز ہونے لگے اورفرماتا ہے کہ ایسے معاہدات بہرحال ناجائز ہیں خواہ اسلام کی تائید کے لئے ہی کیوں نہ ہوں.کیونکہ اگر ساری دنیا کا ایک طریق پر آجا نا تمام امور انصاف پرمقدم ہوتاتواللہ تعالیٰ خود ہی ایسا کرسکتا تھا.وہ تم کو گناہ میں ملوث کیوں کرتا.پس سب دنیا کا اسلام پر جمع کرنابھی ایسامقصدنہیں جس کے لئے یہ طریق اختیار کرناجائز ہو.غرض اس آیت میں یہ بتایاگیا ہے کہ جوقوم بھی جبر سے اورتعدّی سے دنیا کو ایک کرنا چاہے گی وہ کبھی کامیاب نہ ہوگی.اوراس کے ان اعمال کے متعلق اسے پوچھا جائے گا یعنی اس کی اس کو سزاملے گی.مسلمانوں کی تباہی کی بڑی وجہ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ بغیر رضامندی کے زیادہ دیر تک غیر اقوام کسی
Page 188
قوم کے ماتحت نہیں رہ سکتیں اورجوقومیں دوسری قوموں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں آخر اس غلامی کا نتیجہ خود ان اقوام کے ہی خلاف نکلتا ہے اوران اقوام کے اخلاق بگڑجاتے ہیں.مسلمانوں کی تباہی کی بڑی وجہ یہی تھی.ان کی آئندہ نسلیں گھرکے غلاموں ہی سے اخلاق سیکھتی تھیں اوراسی وجہ سے ہوتے ہوتے آخر کا ران کے اخلاق غلاموں کے سے ہوگئے.اگر وہ قرآنی احکام پر عمل کرکے جلد سے جلد غلامی کو مٹادیتے توکبھی یہ دن دیکھناانہیں نصیب نہ ہوتا.ان کی تباہی گویا وَ لَتُسْـَٔلُنَّ کاایک درد ناک نظار ہ تھی.وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًۢا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کرنے کاذریعہ مت بنائو.ورنہ(تمہارا)قدم بعد اس کے کہ وہ(خوب مضبوطی ثُبُوْتِهَا وَ تَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ سے )جم چکا ہو(پھر ) پھسل جائے گااور تم اس بدی کا مزہ چکھو گے کیونکہ تم نے (اس طرح سے اورلوگوں اللّٰهِ١ۚ وَ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۰۰۹۵ کوبھی)اللہ(تعالیٰ)کی راہ سے روکا اور تم پر بڑاعذاب( نازل)ہوگا.تفسیر.معاہدات کی پابندی پر زور اس آیت میں لَا تَتَّخِذُوْۤا اَيْمَانَكُمْ کے الفاظ کو دہرایا ہے.اس میں یہ بتانامقصود ہے کہ گومعاہدات کی بنیاد بدنیتی پر رکھنا اورمعاہدہ توڑنے کی نیت سے کرنا اصولاً بھی براہے لیکن مسلمانوںکے لئے خصوصاً براہے کیونکہ مسلمان دین حق کے حامل ہیں.ان کے خراب رویہ کو دیکھ کر خواہ وہ سیاسی معاملات میں ہی کیوں نہ ہو لوگ دین سے بھی متنفر ہوجائیں گے.اورخود مسلمانوںکے حق میں بھی یہ اچھا نہ ہوگا.کیونکہ اس قسم کی باتوں سے وہ کمزو رہوجائیں گے اوران میں اضمحلال پیداہوجائے گا.تَذُوْقُوا السُّوْٓءَ سے معاہدات کے توڑنے کے نتیجہ کی طرف اشارہ تَذُوْقُوا السُّوْٓءَ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہےکہ اگر تم معاہدات توڑوگے توتم بھی دنیا کے فائدہ کی خاطر دین کوبھی نقصان پہنچائو گے.یہ جو فرمایا کہ ایک قد م قائم ہونے کے بعد پھسل جائے گا.اس میں قدم سے مراد مسلمانو ں کی حکومت کااستحکام ہے اورقدم کی تنکیر عظمت کے اظہار کے لئے ہےاوراس میں مسلمانوں کی حکومت کے قیام کی بشارت ہے.
Page 189
ان آیات میں جو معاہدات پر اس قدر زوردیا گیا ہے.اس میں اس امر کی خبر دی گئی ہے کہ مسلمان ساری دنیا پرچھاجائیں گے.کیونکہ جس قوم کے معاہدات توڑنے سے دنیا میں فساد برپاہو جاتا ہے وہ وہی قوم ہوتی ہے جواپنے زمانہ میں سب اقوام پر غالب ہو.ورنہ کمزور اقوام کو معاہدہ توڑنے کی جرأت ہی نہیں ہوسکتی اورنہ ان کے معاہدہ توڑنے سے دنیاپر کوئی زلزلہ آتا ہے.پس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس عظمت کی خبر دیتے ہوئے نصیحت فرماتا ہے کہ تم اپنے معاہدات کو اچھی طرح نباہنا اورسمجھ سوچ کرمعاہدات کرنا.افسوس ابتدائی زمانہ کے بعد مسلمانوں نے اس راز کونہ سمجھا اورتباہ ہوگئے.ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان کالفظ مجسم اعتبار سمجھاجاتاتھااور کسی اورضمانت کی ضرورت نہ ہوتی تھی مگراب مسلمان کے لفظ سے زیادہ بے اعتبار لفظ کوئی نہیں.اِنَّالِلہِ وَاِنَّااِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ.وَ لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا١ؕ اور تم اللہ (تعالیٰ)کے (ساتھ کئے ہوئے )عہد کے بدلے میں(اس کے مقابل پر )حقیر(اورتھوڑی سی )قیمت اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ (رکھنے والی چیز)مت لو.اگرتم علم رکھتے ہو تو(سمجھ لو کہ )جوکچھ اللہ(تعالیٰ)کے پا س ہے وہ تمہارے لئے اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۰۰۹۶ یقیناً(اس سے بدرجہا )بہترہے.تفسیر.چونکہ اس جگہ ترقیات اورحکومت کی پیشگوئیاں تھیں اورحکومت کے زمانہ میں دشمن سازش کرنے اورجاسوس رکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں.جس کے لئے وہ اپنے مقابل فریق کے آدمیوں کو بڑی بھاری رقوم بھی پیش کرتے ہیں.اوریہ زمانہ مسلمانوں پر بھی آنے والاتھا.اس لئے پہلے سے ہی آگاہ کردیا کہ دیکھناایسی حرکت نہ کرنا.تمہارے لئے کئی قسم کے لالچ پیداہوں گے اورایک زمانہ آئے گاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز دریافت کرنے کے لئے مکہ والے تمہیں رشوتیں بھی پیش کریں گے مگر لَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو دنیا کی قیمت پر فروخت نہ کردینا یعنی کمزوری نہ دکھانا.جوعہد کیا ہے.اس کوضرورپوراکرنا.یہ رشوتیں تو
Page 190
ثمن قلیل ہی ہوں گی.مگرجو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گاوہ تمہارے لئے اس سے کہیں بہترہوگا اورآج تم اس کو جان بھی نہیں سکتے.مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان اس پیشگوئی کوسمجھ بھی نہ سکتے تھے.حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آیت’’سَیُھْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلَّوْنَ الدُّبُرَ.‘‘(القمر:۴۶)اس وقت تک کہ جنگ بد رواقع نہ ہوگئی اورمکہ فتح نہ ہوگیا.میری سمجھ میں پوری طرح نہ آتی تھی(درمنثور سورۃ قمر).مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ١ؕ وَ لَنَجْزِيَنَّ جوکچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوجائے گااورجوکچھ اللہ(تعالیٰ)کے پاس ہے و ہ(ہمیشہ)باقی رہنے والا ہے الَّذِيْنَ صَبَرُوْۤا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰۰۹۷ اور(ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے کہ)جولوگ ثابت قدم رہے ہیں ہم انہیں یقیناًان کے بہترین عمل کے مطابق(ان کے تمام اعمال صالحہ کا )بدلہ دیں گے.حلّ لُغَات.یَنْفَدُ.یَنْفَدُ نَفِدَ سے مضارع کاصیغہ ہے.اورنَفِدَ الشَّیْءُ (یَنْفَدُ نَفَادًا)کے معنے ہیں فَنِیَ وَ ذَھَبَ وَانْقَطَعَ.کوئی چیز فنا ء ضائع اورختم ہوگئی (اقرب)پس یَنْفَدُ کے معنے ہوں گے کہ ختم ہوجائے گا.تفسیر.آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ اس میں یہ بتایاہے کہ رشوتوں کے مال جن کی وجہ سے لوگ قوم سے غداری کرتے ہیں آخر ختم ہوجاتے ہیں.مگر وہ عزت جو اپنی قوم کی ترقی سے ملتی ہے وہ دیرپاہوتی ہے اوربہت بڑی ہوتی ہے.دوسرے یہ بھی بتایا کہ آخر دشمن جو کچھ بھی دے گا محدود مال ہو گا.لیکن وہ انعام جو نیکی اورتقویٰ اوروفاداری کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے ملے گاوہ ہمیشہ رہنے والاہوگا کہ ا س کافائدہ اس دنیاسے گذر کر اگلے جہان کی زندگی تک بھی پہنچے گا.بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ میں اعلیٰ انعام کا اشارہ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَاس میں یہ بتایا ہے کہ ہم کنجوس گاہک کی طرح ردّی چیز کو چن کر باقی کو اس پر قیاس نہ کریں گے.بلکہ جو عمل تمہارے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گے ان کے مطابق تمام اعمال کو قرار دے کر ان کا اجر دیں گے.نیز یہ بھی بتایا کہ ان کابدلہ ان کے اعمال سے زیادہ
Page 191
ہوگا.کیونکہ لکھا ہے کہ ایک نیکی کا اجرکم سے کم دس گنا ملتاہے.لیکن یہ قید لگادی کہ یہ انعام صرف انہی کو ملے گا جو صبر کریں گے یعنی مشکلات سے گھبرائیں گے نہیں اوردین کوبیچیں گے نہیں.مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ جوکوئی مومن ہو نے کی حالت میں مناسب حال عمل کرےگا.مردہوکہ عورت فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً١ۚ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ ہم اس کو یقیناًایک پاکیز ہ زندگی عطاکریںگے اورہم ان( تما م لوگوں)کو ان کے بہترین عمل کے مطابق بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰۰۹۸ ان (کے تمام اعمال صالحہ )کا بدلہ دیں گے.تفسیر.اسلام میں مرد و عورت کے حقوق کی مساوات اس آیت میں ایک طرف تومسلمانوں کو بتایا ہے کہ اسلام میں مرد اورعورت دونوں کے حقوق کو تسلیم کیا گیا ہے.آئندہ جدوجہد میں ہرشخص کو مردہویاعورت اس کے عمل کے برابر بدلہ ملے گااورعورت ومرد میں فرق نہ کیا جائے گا.دوسری طرف کفار کو یہ توجہ دلائی ہے کہ تم عورت کو مارتے ہو تم کو حکومت کس طرح دی جاسکتی ہے.اب تووہ حکومت قائم کی جائے گی جس میں مرد اورعورت دونوں کے حقو ق محفوظ ہوں.اسلام کی سچائی کا یہ کس قد رزبردست ثبوت ہے کہ ہزاروں سالوں کی انسانی زندگی کے بعد اس نے پہلی مرتبہ مرد اورعورت کے حقوق کو تسلیم کیا اوراس کے جاری کرنے کی اس وقت خبر دی جبکہ ابھی مسلمانوں کو حکومت بھی نہ ملی تھی اوراس کے باوجود ظالم دشمن اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کی نگہداشت نہیں کی گئی.
Page 192
فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ اس لئے (اے مخاطب)جب توقرآن پڑھنے لگے تودھتکارے ہوئے شیطان (کے شر)سے (محفوظ رہنے کے الرَّجِيْمِ۰۰۹۹ لئے )اللہ(تعالیٰ)کی پناہ مانگ (لیا کر ).حلّ لُغَات.اِسْتَعِذْ.اِسْتَعِذْ اِسْتَعَاذَ سے امر مخاطب کاصیغہ ہے.اوراِسْتَعَاذَ.عَاذَ سے باب استفعال ہے اورعَاذَ بِہٖ فی کَذَا(یَعُوْذُ عَوْذًا.وَعِیَاذًا)کے معنے ہیں.لَجَأَ اِلَیْہِ وَاعْتَصَمَ.اس کی پناہ لی.تَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْم اَیْ اَلْتَجِیُٔ اِلَی اللہِ وَاَعْتَصِمُ مِنَ الشَّیْطَان.اوراَعُوْذُ بِاللہِ منَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْم کے معنے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ لیتاہوں اورشیطا ن سے بچتاہوں.اِستَعَاذَ بِہٖ مِنْہُ.اِعْتَصَمَ وَلَجَأَ اِلَیْہِ مِنْہُ.اس نے اس کے ذریعہ پنا ہ لی.(اقرب) پس اِسْتَعِذْ کے معنے ہوں گے کہ شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ چاہو.تفسیر.اِذَاقَرَاْتَ کے یہ معنے نہیں کہ جب تو قرآن ختم کیا کرے تومعوّذتین پڑھ لیا کر.کیونکہ وہ سورتیں توقرآن میں شامل ہیں.بہرحال پڑھی ہی جائیں گی ان کو چھوڑ تو نہ دیاجائےگا.پس اس جگہ جیساکہ سنت نبویؐ سے ثابت ہے شروع تلاوت میں اَعُوْذُ بِاللہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ پڑھنے کاحکم ہے.پہلے فرمایاتھا کہ ثابت قدم لوگوں کو یہ یہ عظیم الشان انعامات ملنے والے ہیں.اب اس نعمت کی حفاظت کے لئے ایک گر بتاتاہے اوروہ یہ ہے کہ تم شیطان کے حملو ں سے بچنے کے لئے خدا تعالیٰ کی پنا ہ میں آجا ئو.تاتم ان انعامات کے وارث ہوسکو اوررستہ سے بھٹک نہ جائو.بعض نادانوں نے غلط آراء اورروایات پر بنیادرکھ کر اس آیت کے یہ معنے کئے ہیں کہ یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے او ر اس کی شان نزول یہ ہے.کہ سورۃ النجم کی تلاوت کرتے ہوئے ایک دفعہ آپ کی زبان پر بعض شرکیہ کلمات شیطان نے جاری کردئے تھے.نعوذ باللہ من ذالک.جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیاکہ آئندہ جب قرآن پڑھاکروتوپہلے اعوذ ضرور پڑھ لیا کرو تاشیطان پھر تمہاری زبان پر کو ئی کلمہ ء شرک جاری نہ کردے.(تفسیر القرآن از ویری زیر آیت ھذا)
Page 193
حالانکہ اول تویہ واقعہ ہی غلط ہے (اس واقعہ پر ا صل گفتگو اس کے اصل مقام یعنی سورئہ حج میں ہوگی)دوم ا س آیت کے سیاق و سباق سے اس مضمون کا کوئی جو ڑ ہی نہیں.بھلا کو ن عقلمند اس امر کو تسلیم کرسکتاہے کہ واقعہ ہواہو سورۃ النجم کی تلاوت پر.اس کا ذکر ہو اہو سورۃ حج میں اوراعوذ پڑھنے کے لئے سورۃالنحل میں تاکید کی جاوے.اور تاکید بھی اسلامی غلبہ کے ذکرمیں کی جائے تاکہ کسی کا ذہن اس کے مضمون کی طر ف جاہی نہ سکے.نَعُوْذُ بِاللہِ مِنْ ذَالِکَ.میں جیساکہ اوپر بتاچکاہوںیہ آیت اپنے مضمون ماسبق کے ساتھ پوری طرح مطابق ہے اور کسی دوسرے واقعہ کی طرف اسے منسوب کرنا ظلم ہے.پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میراشیطان مسلما ن ہوگیا ہے وہ مجھے سوائے خیر کے کسی چیز کاحکم ہی نہیں دیتا(مسند احمد بن حنبل مسند ابن عباس ؓ) اس ارشاد کی موجودگی میں کوئی عقل مند کس طرح تسلیم کرسکتا ہے کہ شیطان نے آپ کی زبان پر شرک کے کلمات جاری کروائے تھے.مسلمان توتوحید کاقائل ہوتا ہے.پس آپ کاشیطان جب موحد ہوگیا تھا تواگر اسے کوئی طاقت تھی بھی توبھی وہ آ پ کی زبان پر مشرکانہ کلمات جاری نہیں کرسکتا تھا.پس اس فرضی واقعہ کو اس آیت پرچسپاں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بہتان ہے.قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ کی حکمت یہ سوال کہ قرآن سے پہلے استعاذہ(اعوذپڑھنے)کی کیا ضرورت ہے ؟ ا س کا جواب یہ ہے.کہ چور وہیں آتاہے جہاں خزانہ ہو.اوراسی سے مقابلہ کرنے کی فکر کی جاتی ہے جس سے خطرہ ہو.قرآن کریم ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جس کے مٹانے کے لئے شیطان تڑپتاہے اور وہی ہتھیار ہے جس سے اس کاسرکچلاجاتاہے.پس شیطان اورشیطانی لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو دور رکھیں.اس وجہ سے اس کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کاحکم دیا.اس حکم سے یہ بھی نتیجہ نکالاجاسکتاہے کہ جب قرآن کریم سے پہلے بھی استعاذہ کاحکم ہے.توباقی سارے کاموں سے پہلے توبدرجہ اولیٰ استعاذہ کرلیناچاہیے.اسلامی ترقیات کے ساتھ تعوذ کا گہر اتعلق اس سوال کا جواب کہ یہ حکم اس موقعہ پرکیوں رکھا گیا ہے ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ سب سے پہلا موقعہ ہے کہ اسلامی حکومت کی ایسی وضاحت سے خبردی گئی ہو.پہلے بھی اشارات تھے مگر اس سے پہلے اس قدروضاحت نہ ہوئی تھی.اورجب دنیو ی ترقیات کا ذکر ہوتوبعض کمزورطبائع دینی ضرورتوں سے غافل ہو کر دنیوی امورکی ادھیڑ بن میں پڑ جاتی ہیں پس چونکہ اس سور ۃ میں دنیو ی ترقیات کی خبردی گئی تھی.ساتھ ہی مسلمانوں کوحکم دے دیاگیا کہ آئندہ جب قرآن کریم پڑھنے لگو اس سے پہلے تعوذ
Page 194
کرلیا کرو.تاکہ دنیوی فتوحات کی پیشگوئیاںتمہاری توجہ کو اپنی طرف پھراکرتم کو دین کے اعلیٰ مقاصد سے غافل نہ کردیں.اوردنیا دین پر مقدم نہ ہوجائے.اللہ اللہ !کیاپاک کلام ہے اوراس میں کس طرح مومنوں کے ایما ن کی حفاظت کے ساما ن پیداکئے گئے ہیں.اوراس کے باوجود دشمن کہتا ہے کہ لالچ دے دےکر قرآن کریم نے لوگوںکو اسلام کی طرف راغب کیا تھا.(ستیارتھ پرکاش اردو ترجمہ باب ۱۴ صفحہ ۷۰۱).اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ (سچی )بات یقیناًیہی ہے کہ جولوگ ایمان لائے ہیں اوراپنے رب (کی پناہ)پر بھروسہ رکھتے ہیں.ان پر اس يَتَوَكَّلُوْنَ۰۰۱۰۰ کاکوئی تسلط نہیں ہے.تفسیر.انجیلی تعلیم کے مقابل قرآن مجید کی دنیوی کاموں میں حصہ لینے کی تعلیم بعض لوگوں کاخیال ہے کہ دنیا میں پڑ کر انسان خدا تعالیٰ سے محبت کرہی نہیں سکتا.چنانچہ حضرت مسیح کی طرف انجیل میں یہ قول منسوب کیا گیا ہے.(۱)’’اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانااس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو ‘‘.(متی با ب۱۹آیت ۲۴) نیز (۲)’’دولت مندوں کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیسامشکل ہے کیونکہ اونٹ کاسوئی کے ناکے سے نکل جانااس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو.‘‘(لوقا باب ۱۸آیت ۲۴و۲۵) اس خیال کے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوسکتاتھاکہ دنیا کے متعلق خبریں پڑھنے سے بعض لوگوں کے ایما ن میں کمزوری پیدا ہونے کااحتمال ہوسکتاتھاتومسلمانوں کو دنیوی فتوحا ت اورحکومت کی خبر دی ہی کیوں گئی ؟ اس کا جواب یہ دیا کہ شیطان کاقبضہ کمزوروں پرہوتا ہے.مومن دنیا میں پڑ کر بھی دین کی طرف سے غافل نہیں ہوتا.پس اس جگہ ہم صرف کمزوروںکو ہوشیارکرتے ہیں.یہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ مضبوط ایمان والے بھی دنیا میں پڑ کر نجات سے محروم ہوجاتے ہیں.گویااسلام کی تعلیم اس بارہ میں یہ ہے کہ دست درکارودل بایار.اوریہی مقام اعلیٰ
Page 195
مقام ہے.اسی وجہ سے اسلام نے دنیاکو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ دنیا کے کاموں میں حصہ لیتے ہوئے اس کی اصلاح کاحکم دیا ہے.اگرنیکوں کودنیا سے علیحدہ رکھا جائے توظاہر ہے کہ دنیا کی اصلاح کبھی ہوہی نہیں سکتی.اگر ایسے لوگوں کے ہاتھو ں میں دنیا کی باگ آئے جوباوجود دنیا پر تصرف حاصل کرلینے کے انصاف اورعد ل اورتقویٰ قائم رکھیں تبھی دنیا کی اصلاح ہوسکتی ہے.اوردوسروں کے لئے نیک مثال قائم ہوسکتی ہے.دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورآپ کے صحابہ کے ہاتھ جب دنیا کانظم و نسق آیا.توانہوں نے کس طرح اس میں پڑ کراس سے علیحدہ رہنے کانمونہ دکھایا.اورایک ایسی شاندارمثال قائم کی جو اب بھی کہ اس پر تیرہ سوسال گذر چکے ہیں.اہل عقل کے دلوں میں گدگدیاں پیداکردیتی ہے.اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ اس کاتسلط صرف ان لوگوں پر (ہوتا)ہے.جواس سے دوستی رکھتے ہیں.اورجو اس کی وجہ مُشْرِكُوْنَؒ۰۰۱۰۱ سے شرک کرتے ہیں.تفسیر.هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ میں ضمیر بہ کا مرجع هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ.بِہٖ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جاسکتی ہے جس کا ذکر رَبِّھِمْ کے الفاظ میں پہلی آیت میں ہوچکاہے.اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ اس کاتصرف ان لوگوں پرہے جو اپنے رب کے شریک قرار دیتے ہیں.اوراس ضمیرکامرجع شیطان بھی ہوسکتا ہے.اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ وہ شیطان کے سبب سے شرک میں مبتلاہوجاتے ہیں.اس آیت میں یہ بتلایاہے کہ شیطان کا قبضہ اورتصرف اس کے دوستوں پرہوتاہے جوشخص استعاذہ کرتاہے وہ توگویااس سے دشمنی کااعلان کرتاہے.اس لئے وہ اس کے قبضہ سے نکل جائے گا.استعاذہ کے حکم میں آنحضرت ؐ کا ذکر نہیں ہو سکتا اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ والی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نہیں.کیونکہ اس میں تویہ بتایا ہے کہ اس کا قبضہ اپنے دوستوں پر ہوتاہے نہ کہ ان لوگوں پر جو خدا تعالیٰ پر توکل کرنےوالے ہوں.اورآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متواتر اعلان ہوچکاہے کہ ’’میراتوکل توصرف خدا پر ہے ‘‘.پس اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوہی نہیں
Page 196
سکتا.دوسرے لوگوں کاہی ذکر ہے.وَ اِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ١ۙ وَّ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اورجب ہم کسی نشان کی جگہ پر کوئی اورنشان لاتے ہیں اور(اس میں کیا شک ہے کہ )اللہ(تعالیٰ)جوکچھ اتارتاہے قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ١ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ اس (کی ضرور ت)کووہ (سب سے)بہترجانتاہے تو(مخالفین )کہتے ہیں کہ تومفتری ہے (مگرحقیقت یوں ) لَا يَعْلَمُوْنَ۰۰۱۰۲ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے.حلّ لُغَات.یُنَزِّلُ.یُنَزِّلُ نَزَّلَ سے مضارع واحد مذکرغائب کاصیغہ ہے.مزید تشریح کے لئے دیکھو سورۃ حجرآیت نمبر ۲۳.نُنَزِّلُ نَزَّلَ سے مضارع جمع متکلم کاصیغہ ہے.اور نَزَّ لَہُ کے معنے ہیں.صیَّرَہُ نَازِلًا اس کو اترنے والا کردیا.یعنی ایسی حالت میں کردیا کہ اُترے.اَلْقَوْمَ:اَنْزَلھُمُ الْمَنَازِلَ.لوگوں کو ان کی جگہوں پر اتارا.اَلشَّیْءَ:رَتَّبَہُ.کسی چیز کو مرتب کیا.عِیْرَہُ:قَدَّرَلَھَا الْمَنَازِلَ.قافلہ کے امام نے قافلہ کے لوگوں کے لئے جگہیں مقرر کردیں (اقرب) تَنْزِیْلٌ اصل میں آہستہ آہستہ اتارنے کو کہتے ہیں.تفسیر.آیت کے معنی اور اس سے مراد اٰیَۃً کے اصل معنے نشان کے ہیں.گوقرآن کریم کے جملوں کو بوجہ اس کے کہ ان میں سے ہرایک اپنی ذات میں ایک نشانِ ہدایت ہے.آیت کہتے ہیں.مگراٰیَۃً کے معنے کتاب کے فقرے کے نہیں ہوتے.اورقرآن کریم میں کسی جگہ پراس لفظ کا استعمال یقینی طورپر ان معنوں میں نہیں ملتا.اگربعض جگہ آیت کالفظ جملہ کے معنوں میں نظر بھی آتاہے تووہ بھی یقینی نہیں کیونکہ اس جگہ دلیل اورنشان کے معنے بھی ہوسکتے ہیں.ہاں مسلمانوں میں شروع سے اس لفظ کا استعمال ان معنوں میں مروّج چلاآتاہے.صحابہ بھی قرآنی جملوں کو اٰیۃ کہہ کرپکارتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں بھی یہ استعمال پایاجاتا ہے (بخاری کتاب التفسیر باب تفسیر ان الصفا و المروة...).اس استعمال سے دھوکاکھاکر بعض مفسرین نے اس
Page 197
آیت کے یہ معنے کئے ہیں کہ جب قرآن کریم کی ایک آیت منسوخ کرکے دوسری آیت نازل کی جاتی.توکفار اعتراض کرتے کہ تم جھوٹے ہو.اگرقرآن خدا تعالیٰ کاکلام ہوتا تواس کی آیتیں منسوخ کیوں ہوتیں (تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا).میرے نزدیک یہ معنے درست نہیں کیونکہ تاریخ سے کوئی ایک آیت بھی ثابت نہیں ہوتی جسے بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت رکھی گئی ہو.اگرایسا ہوتا توقرآن کے سینکڑوں حافظ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم کوحفظ کرلیاتھااس امر کی شہادت دیتے کہ پہلے ہمیں فلاں آیت کے بعد فلاں آیت یاد کروائی گئی تھی.لیکن اس کے بعد اسے بدل کر فلاں آیت یاد کرائی گئی.اس قسم کی شہادت کانہ ملنا بتاتا ہے کہ اس بارہ میں جس قدرخیالات رائج ہیں ان کی بنیاد محض ظنیات پر ہے نہ کہ علم پر.میں اس کا منکر نہیں کہ بعض احکام زمانہ نبوی ؐ میں بدلے گئے ہیں.مگرمجھے قرآن کریم کے کسی حکم کی نسبت ثبوت نہیں ملتا کہ پہلے اورطرح ہو اوربعد میں بدل دیاگیاہو.میرے نزدیک جو احکام وقتی ہوتے تھے وہ غیر قرآنی وحی سے نازل ہوتے تھے.قرآن کریم میں اترتے ہی نہ تھے.اس لئے قرآن کریم کوبدلنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی تھی.ناسخ منسوخ کے متعلق بحث اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگرآیاتِ قرآنیہ کوکبھی بدلا نہیں گیاتواس آیت کے کیا معنے ہوئے ؟تواس کا جواب یہ ہے کہ اٰیَۃً کے وہ معنے جن میں یہ لفظ بالعمو م قرآن کریم میں استعمال ہواہے.نشان آسمانی کے ہیں.اور وہی اس جگہ مراد ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم ایک نشان بدل کر اس کی جگہ دوسرانشان لے آتے ہیں اورایساکرناقابل اعتراض نہیں ہوتاکیونکہ اس امرکو تواللہ تعالیٰ ہی جانتاہے کہ کونسانشان کس موقعہ کے لئے مناسب ہے توکفار اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں اورکہتے ہیں کہ تُوتوجھوٹاہے.مگریہ اعتراض ان کاجہالت پرمبنی ہوتاہے.یہ وہ قانون ہے جس کاظہور ہر نبی کے زمانہ میں ہوتاہے.یعنی ہرنبی کو بعض انذاری باتیں بتائی جاتی ہیں جودرحقیقت مشروط ہوتی ہیں.مخاطب قوم کے قلوب کی حالت سے.اگروہ اپنے دل کی حالت بد ل لیں تووہ انذار کی خبر بھی ٹل جاتی ہے.جیسے قرآن کریم میں حضرت یونس ؑ کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی ہلاکت کی خبر حضرت یونسؑ کی معرفت دی گئی.مگربعد میں ان کی توبہ کی وجہ سے اسے بدل دیاگیا.(یونس آیت ۹۹) انذاری پیشگوئیاں مشروط ہوتی ہیں یہ عام قانون انذاری پیشگوئیوں کے متعلق ہے کہ اگر مخالف توبہ کرلیں تومقدرعذاب کو روک دیاجاتا ہے.ہاں وعدہ کی خبر ضرور پوری ہوکر رہتی ہے.مگراس کے متعلق بھی سنت اللہ یہ ہے کہ اگروہ قوم جس سے وعدہ ہو پوری قربانی سے کام نہ لے یاپوری فرمانبرداری نہ دکھا ئے تواس کے پوراہونے میں
Page 198
تاخیر کردی جاتی ہے.جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قو م کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے متواترحضرت موسیٰ ؑکی نافرمانی کی تووہ ارضِ موعودہ جس میں داخل کرنے کے لئے حضرت موسیٰ ؑ انہیں مصر سے نکال کر لائے تھے چالیس سال تک کے لئے اس کی فتح روک دی گئی اس کے موعود ہونے کا ذکر ان الفاظ میں کیاگیاہے.یٰقَوْمِ ادْخُلُوْاالْاَرْضَ الْمُقَدَّسَۃَ الَّتِیْ کَتَبَ اللّٰہُ لَکُمْ(المائدۃ :۲۲)اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہوجائو جوخدا تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ رکھی ہوئی ہے.اس کے بعد یہود کی نافرمانی کا ذکرکرکے فرماتا ہےقَالَ فَاِنَّھَامُحَرَّمَۃٌ عَلَیْھِمْ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً.یَتِیْھُوْنَ فِی الْاَرْضِ فَلَاتَاْسَ عَلَی الْقَوْمِ الْفٰسِقِیْنَ(المائدۃ:۲۷)یعنی جب انہوںنے نافرمانی کی تواللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب یہ ملک چالیس سال تک کے لئے بنی اسرائیل پرحرام کردیاگیاہے.پس تونافرمان قوم کی حالت پرافسوس نہ کر.اس آیت سے معلوم ہوتاہے کہ وعدہ کو ٹلادیاگیاہے.لیکن اسے منسوخ نہیں کیاگیا.کیونکہ وعدہ خدا تعالیٰ منسوخ نہیں کیاکرتا.مذکورہ بالاقانون کے مطابق انذارکی پیشگوئی جب کبھی ٹلتی ہے توکفار شور مچادیتے ہیںکہ دیکھو یہ جھوٹاہے.اگر سچا ہوتا تو کیوں اس کی بات پوری نہ ہوتی.ایسے ہی اعتراضات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیاکرتے تھے.اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیات توکسی غرض اورمقصد کے لئے نازل ہوتی ہیں.جب ہم دیکھیں کہ ایک شخص نے اپنی اصلاح کرلی ہے توہم اس کے متعلق اپنے حکم کوبھی بدل دیتے ہیں اوراس کی سزامنسوخ کردیتے ہیں اس کی جگہ اس کے لئے اپنی رحمت کا نشا ن دکھاتے ہیں.کیونکہ ہماری غرض سزادینا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہوتاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی مواقع پیش آئے ہیں.مثلاً یہی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کی نسبت فرماتا ہے لَایُؤْمِنُوْنَ(البقرۃ:۷)لیکن بعد میں ان میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے.یہ عذاب کی خبر تھی اس وجہ سے جن جن لوگوں نے خشیت اللہ پیداکرلی ان کاعذاب بدل دیاگیااوران کو ایمان عطاہوگیا.جھوٹ کی تعریف بظاہر یہ مسئلہ بالکل صاف ہے لیکن ہمیشہ ہی لو گ اس بارے میں ٹھوکر کھاتے ہیں.اوراس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بات بدلنے کو جھوٹ سمجھتے ہیں.حالانکہ سزاکو بدلنا جھوٹ نہیں ہوتا.وعدہ کو بدلنا جھوٹ
Page 199
ہوتاہے.چنانچہ عربی زبان میں وعد ہ کے بدلنے کو جھوٹ کہتے ہیں.وعید یعنی عذاب کی خبر کو بدلنے کو جھوٹ نہیں کہتے بلکہ اسے رحم اوراحسان کہتے ہیں.اقرب میں لکھا ہے اَلْخَلْفُ فِی الْوَعْدِ عِنْدَ الْعَرَبِ کِذْبٌ وَفِی الْوَعِیْدِ کَرَمٌ (اقرب).یعنی وعدہ کابدلنا عربوں کے نزدیک جھوٹ کہلاتاہے اوروعید یعنی سزاکی خبر کابدلنا شرافت اوراحسان کہلاتا ہے.غرض ایک معنے تواس آیت کے یہ ہیں کہ ہم وعید کی خبروں کوبعض دفعہ بدل دیاکرتے ہیں.کفاراس پر اعتراض کرتے ہیں.لیکن ان کااعتراض صحیح نہیں.ایساکرناحکمت کے عین مطابق ہے اس میں کسی کاحق نہیں ماراجاتا کہ قابل اعتراض ہو.ان معنوں کے روسے اس آیت کا تعلق ان انذاری آیات سے ہوگاجوپہلے بیان ہوچکی ہیں.اس آیت کے ایک اور معنی ایک اورمعنے بھی اس آیت کے ہیں اورو ہ ترتیب قرآن کو مدنظررکھتے ہوئے ا س مقام پر زیادہ چسپاں ہوتے ہیں اوروہ یہ کہ جیساکہ میں بتاچکاہوں اس سورۃ میں کلام الٰہی کی ضرورت کے دلائل بیان کئے جارہے ہیں اوراس کے ثبوت میں پہلے انبیاء کو بھی پیش کیاگیاہے.مثلاً اسی سور ۃ کے آٹھویں رکوع میں فرماتا ہے کہ تَاللّٰہِ لَقَدْاَرْسَلْنَآ اِلیٰٓ اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِکَ(النحل:۶۴)ہمیں اپنی ذات ہی کی قسم کہ جوتجھ سے پہلے قومیں گذر چکی ہیں ان میں بھی ہم رسول بھیج چکے ہیں.پھر رکوع ۱۲ میں فرماتا ہے وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ کُلِّ اُمَّۃٍ شَھِیْدًا عَلَیْھِمْ مِنْ اَنْفُسِھِمْ (النحل:۹۰)یعنی اس دن کویاد کرو جبکہ ہم ہرقوم کے خلاف اسی قوم کا نبی گواہ بناکر کھڑا کریں گے.نسخ آیات کے ایک لطیف معنی اس میں ا س طرف اشارہ تھاکہ سب قوموں میں نبی مبعوث ہوچکے ہیں.توچونکہ گذشتہ انبیاء کے وجود کو کلام الٰہی کی ضرورت کے ثبوت میں پیش کیاگیاتھا جب کفارہرطرف سے عاجز آگئے توانہوں نے یہ دلیل اسلام کے خلاف پیش کی کہ اگرپہلے بھی نبی گذر چکے ہیں توچاہیے تھاکہ ان کی تعلیم اوراسلام کی تعلیم ایک ہی ہوتی مگر اس میں توان کی تعلیمو ں کے خلاف تعلیم بھی پائی جاتی ہے پس معلوم ہواکہ محمد(رسول اللہ) جواپنے تسلیم کردہ نبیوں کے خلاف باتیں کہتے ہیں جھوٹے ہیں ورنہ یہ کس طرح ہوسکتاتھا کہ خدا تعالیٰ ان نبیوں کو کچھ کہے اوراس کو کچھ اَورکہے.سواس اعتراض کوبیان کرکے اس کا جواب دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے کس زمانہ میں کیا نازل کرنا چاہیے.یعنی پہلے انبیاء کی تعلیم سے جہاںجہاں قرآن کریم نے اختلاف کیا ہے.اس کی یہ وجہ نہیں کہ اس سچی تعلیم کی قرآن
Page 200
نے مخالفت کی ہے.بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی طرف کلام نازل ہواہے وہ پہلے لوگوں سے مختلف ہیں اورایک ہی شخص مختلف لوگوں کو ان کے حالات کے مطابق مختلف حکم دیتاہے اوردے سکتا ہے اوریہ اختلاف اس امر کی دلیل کبھی اور کسی صورت میں نہیں قرار دیاجاتاکہ چونکہ مختلف حکم ہیں حکم دینے والے بھی مختلف ہیں.اختلاف ہمیشہ حکم دینے والوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہی نہیں پیدا ہوتابلکہ بعض دفعہ اختلاف ان لوگوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جنہیں حکم دیاگیاہو.جب مخاطب مختلف قابلیتوں کے ہوں تو ایک ہی حکم دینے والا مختلف لوگوںکو ان کے حسب حال مختلف حکم دیتاہے.اصل سوال تویہ ہوناچاہیے کہ قرآن کی تعلیم زمانہ کے حسب حال ہے یانہیں.اگروہ زمانہ کے حسب حال ہے تواس اختلاف سے علم الٰہی کاثبوت ملانہ اس کاکہ محمد رسول اللہ پر کلام نازل کرنے والا کوئی اَورہے اورپہلے نبیوں پر کلام نازل کرنے والاکوئی اَور.یہ معنے اگلی آیات سے بھی بالکل مطابق آتے ہیں اس لئے یہی اس موقعہ کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہیں.ہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس صورت میں اٰیَۃً کے معنے پہلی کتا ب کے لئے جائیں گے یعنی جب ایک کتاب کی جگہ دوسر ی کتاب کو بدلاجاتاہے اورکتاب بھی آیت ہوتی ہے.بلکہ سب سے بڑا معجزہ انبیاء کا کتاب ہی ہوتاہے.قرآن کریم کے دیگر کتب کے مصد ق ہونے سے مراد تعجب ہے کہ یہ اعتراض آج تک قرآن کریم پر ہورہا ہے.چنانچہ مسیحی مصنف آج تک یہی اعتراض کرتے چلے جارہے ہیں کہ جب قرآن کریم کتب سابقہ کا مصدق ہونے کادعویٰ کرتاہے توان سے اختلاف کیوں کرتاہے.یہ ا س با ت کا ثبوت ہے کہ قرآن نعوذ باللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )کابنایاہواہے اورانہوں نے پہلی کتب سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسی باتیں لکھ دی ہیں جوپہلی کتب کے خلاف ہیں.(تفسیر القرآن از ویری سورہ بقرہ آیت ۹۰ ).بعض مفسرین نے اس آیت کے معنے کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اس میں سورۃ النجم کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت شیطان نے بعض آیتیں بلند آواز سے آپ کی تلاوت کے درمیا ن میں پڑھ دی تھیں اول تویہ واقعہ ہی سرے سے باطل ہے جیسا کہ انشا ء اللہ اس کے موقعہ پر بتایاجائے گا.لیکن اگربفرض محال اسے تسلیم بھی کرلیا جائے توبھی اس آیت سے اس کاکوئی تعلق نہیں.کیونکہ اس آیت میں تویہ ذکر ہے کہ جو آیت بدلی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اورجس نے بدلاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی.اورجس واقعہ کو وہ اس آیت پر چسپاں کرتے ہیں ا س میں خود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو آیات بدل گئیں وہ شیطان کی تھیں پس ان کی اپنی تشریح ہی ثابت کرتی ہے کہ اس فرضی واقعہ کااس آیت سے کوئی تعلق نہیں.
Page 201
علاوہ ازیں اگلی آیت بھی ان معنوں کو ردّکررہی ہے کیونکہ اس آیت میں اس اعتراض کادوسرا جواب دیاگیا ہے جو یہ ہے کہ اس قرآن کوروح القدس نے اتاراہے.ا ب یہ ظاہر ہے کہ روح القدس کااتارنا کفارکے اس اعتراض کا جواب نہیں ہوسکتا کہ پہلے اس نے نعوذباللہ مشرکانہ تعلیم دی تھی اب اسے بدل کیوں دیاگیا ہے.کیونکہ روح القدس کااتارنا اس کے محفوظ ہونے کی دلیل توبن سکتاہےشیطان کی ملونی اورا س کے بعد اس کی منسوخی کی دلیل نہیں بن سکتا.قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ تو(ایسے معترض سے )کہہ (کہ)روح القدس نے اسے تیرے رب کی طرف سے حق(وحکمت )کے ساتھ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى وَّ اتاراہے تاکہ جو لو گ ایمان لائے ہیں انہیں وہ(ایمان پر)ہمیشہ کے لئے قائم کردے اور(نیز اس نے )کامل بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۠۰۰۱۰۳ فرمانبرداروں کی(مزید)رہنمائی کے لئے اور(انہیں )بشارت دینے کے لئے اسے اتاراہے.حلّ لُغَات.اَلْحَقّ اَلْحَقُّ کے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر۲۳.رعد آیت نمبر ۱۵.رَبّ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۴.اَلْحَقُّ.حَقَّ کا مصدر ہے.اور حَقَّہُ حَقًّا کے معنے ہیں غَلَبَہُ عَلَی الْـحَقِّ.حق کی وجہ سے اس پر غالب آیا.وَالْاَمْرَ اَثْبَتْہُ وَاَوْجَبَہُ.کسی امر کو ثابت کیا اور واجب کیا.کَانَ عَلٰی یَقِیْنٍ مِنْہُ.کسی معاملہ پر یقین سے قائم تھا.اَلْخَبْرَ.وَقَفَ عَلٰی حَقِیْقَتِہِ اور حَقَّ الْخَبْرَ کے معنے ہوں گے اس کی حقیقت سے آگاہ ہوا اور اَلْحَقُّ کے معنے ہیں ضِدُّ الْبَاطِلِ سچ.اَلْاَمْرُ الْمُقْضِیُّ فیصلہ شدہ بات.اَلْعَدْلُ.عدل.اَلْمِلْکُ.ملکیت.اَلْمَوْجُوْدُ الثَّابِتُ.موجودہ قائم.اَلْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ.یقین.اَلْمَوْتُ.موت اَلْحَزْمُ دانائی.(اقرب) الرَّبُّ.مالک، آقا یا مطاع مستحق یا صاحب الشئے یعنی کسی چیز والا.رَبَّ الشَّیْءَ.جَمَعَہٗ اس چیز کو جمع کیا مَلَکَہٗ اس کا مالک ہوا.اَلْقَوْمَ سَاسَھُمْ وَکَانَ فَوْقَھُمْ قوم پر حکومت اور سیاست کی.النِّعْمَۃَ : زَادَھَا نعمت کو
Page 202
بڑھایا.اَلْاَمْرَ: اَصْلَحَہٗ وَاَتَمَّہٗ کام کو درست اور مکمل کیا.اَلدُّھْنَ: طَیَّبَہٗ وَاَجَادَہٗ.تیل میں عمدگی اور خوبی پیدا کی.اَلصَّبِیَّ: رَبَّاہُ حَتّٰی اَدْرَکَ بچہ کی تربیت کی حتیٰ کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا.(اقرب) یُثَبِّتُ.یُثَبِّتُ ثَبَّتَ سے مضارع واحد مذکر غائب کاصیغہ ہے.ثَبَّتَ کے معنوںکے لئے دیکھو ابراہیم آیت۲۷.یُثَبِّتُ ثَبَّتَ کا مضارع ہے.جس کا مجرد ثَبَتَ ہے اور ثَبَتَ الْاَمْرُ عِنْدَ فُلَانٍ کے معنے ہیں تَحقَّقَ وَ تَاَکَّدَ.کوئی امر کسی کے نزدیک یقینی طور پر ثابت ہو گیا.ثَبَتَ فُلَانٌ عَلَی الْاَمْرِ.دَاوَمَہُ.کسی کام پر دوام اختیار کیا.وَاثْبَتَہ وَثبَّتَہُ.جَعَلَہُ ثَابِتًا فِیْ مَکَانِہِ لَایُفَارِقُہُ.اور اَثْبَتَہُ اور ثَبَّتَہُ کے معنے ہیں اس کو اس کی جگہ پر ایسے طور پر ثبات بخشا اور مضبوط رکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے.سو ثابت کے معنے ہوں گے اپنی جگہ پر مضبوط رہنے والا.(اقرب) ھُدًی:ھُدًی ھدٰی کامصدر ہے ھدٰی کے لئے دیکھو رعدآیت نمبر۲۸.یَھْدِی ھُدًی سے ہے اور ھَدَاہُ الطَّرِیْقَ وَاِلَیْہِ وَلَہُ کے معنے ہیں بَیَّنَہُ لَہُ وَعَرَّفَہُ بِہِ.راستہ دکھایا ، بتایا اور واضح کیا.ھَدٰی فُلَانًا.تَقَدَّمَہُ اس کے آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لے گیا.ھَداہُ اللہُ اِلَی الْاِیْمَانِ: اَرْشَدَہُ.ایمان کی طرف رہنمائی کی.(اقرب) تفسیر.قرآن مجید کا پہلی کتب سے اختلاف اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل نہیں اس آیت میں کفار کے اعتراض کا ایک اورجواب دیاہے.پہلی آیت میں تویہ جواب دیاتھا کہ یہ تعلیم زمانہ کے مطابق ہے.اس لئے اگر بعض مواقع پر اس کو پہلی کتب سے اختلاف ہے تویہ اس کے جھوٹاہونے کی دلیل نہیں.بلکہ اس امرکی دلیل ہےکہ اب زمانہ بدل گیا ہے.اب بعض اَورجواب دیتاہے.پہلی کتب سے اختلاف رکھتے ہوئے قرآن مجید کے سچا ہونے کے چاردلائل (۱)اس کتاب کو روح القدس نے اتاراہے یعنی اس کلام میں نہایت پاکیزہ تعلیم ہے.اگریہ مفتری کاکلام ہوتا توافتراء کرنے والے کی کوئی غرض تو اس کلام میں نظرآتی.لیکن ساراقرآن پڑھ جائو اس میں محمد رسول اللہ ؐ کی اپنی کوئی غرض تم کو نظرنہ آئے گی.بلکہ اس کلام کے پیچھے ایک پاکیزگی کی روح کام کرتی ہوئی تم کو دکھائی دے گی.اس پاکیزگی کی روح سے تم سمجھ سکتے ہو کہ جہاں اس کو پہلی کتب سے اختلاف ہو اوراس اختلاف کی کوئی توجیہ نہ ہوسکے تویہی مانناپڑے گاکہ وہ کتب بگڑ گئی ہیں.یہ نہیں کہاجاسکتاکہ قرآن خدا کاکلام نہیں.کیونکہ یہ نہیں ہوسکتا کہ خدائی کلام توپاکیزگی کی روح
Page 203
سے خالی ہو اورمفتری کاکلام پاکیزگی کی روح سے معمو رہو.(۲)دوسراجوا ب اس میں یہ دیا گیا ہے کہ یہ کلام حق پر مشتمل ہے.جہاں کہیں اس کلام نے پہلی کتب سے اختلاف کیا ہے.اگر وہ اختلاف زمانہ کے بدلنے کے سبب سے نہیں توتم دیکھو گے کہ عقلِ انسانی اسی بات کی تصدیق کرے گی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اوراسے رد کرے گی جو پہلی کتب میں بیان ہواہے.یہ بھی ایک زبردست ثبوت قرآن کریم کی سچائی کاہے.مثلاً حضرت ہارون کاواقعہ ہی لے لو.قرآن میں لکھاہے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا (طہ:۹۱).اب اول توعقلاً ایک نبی کی طرف شرک کامنسوب کرنا کسی صورت میں جائز نہیں.لیکن عقلی بحث کوجانے دوخود بائبل اپنے اس بیان کی تردید کررہی ہے.کیونکہ جنہوں نے بچھڑابنایاتھا بائبل کے بیان کے روسے انہیں قتل کروایاگیاتھا.لیکن اس واقعہ کے معاً بعد ہارونؑ سے بائبل کے رو سے یہ سلوک کیاگیا کہ کہانت ان کی نسل کے لئے مخصوص کردی گئی اورانہیں اللہ تعالیٰ نے خا ص عزت بخشی.یہ سلوک جو ان سے بچھڑے کے واقعہ کے معاً بعد بائبل میں بیان ہواہے بتاتاہے کہ اس موقعہ پر ان کارویہ قابل تعریف تھا.اوربائبل نے جو شرک میں شمولیت ان کی طرف منسوب کی ہے خود اس کی اپنی شہادت کے روسے باطل ہے.(خروج باب ۴۰ آیت ۱۲تا۱۵باب ۳۲ آیت ۲۷،۲۸) غرض قرآن کریم کو جہاں جہاں بھی پہلی کتب سے اختلاف ہے اس کی بات کی عقلاً یانقلًاتصدیق ہوجاتی ہے.اوراس کے خلاف بیانات کی تردید یاعقل کردیتی ہے یانقل یادونوں ہی سے اس کی تردید ہوجاتی ہے.پس اس امر کی موجودگی میں پہلی کتب سے اس کااختلاف اس بات کی علامت نہیں کہ قرآن کریم کومحمدؐ رسول اللہ نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا.بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ تازہ بتازہ محفوظ کلام ہے اورپہلے کلام محرّف مبدّل ہوگے ہیں.(۳)تیسری دلیل اس اعتراض کے جواب میں اس آیت میں یہ دی گئی ہے کہ قرآن ہدایت مجسم ہے.یعنی اللہ تعالیٰ اوربندے کے درمیان صحیح تعلق قائم کرتا ہے اوراسے خدا تعالیٰ تک پہنچاتاہے اوریہ کام افتراءوالے کلام سے ناممکن ہے.پس جب اس پر چل کر انسان خدا سے تعلق پیداکرلیتا ہے.اورپہلی کتب سے نہیں.تومعلوم ہواکہ گووہ نزول کے لحاظ سے سچی کتب تھیں مگر موجود ہ زمانہ کے لحاظ سے وہ مردہ ہیں.اوراس غرض کوپورانہیں کررہیں جوان سے متوقع ہے.پس اختلاف کی صورت میں ان کاقول غلط ہے اورقرآن کا درست.(۴)چوتھی دلیل یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ مومنوں کے لئے بشارت ہے یعنی اس پر چل کرانسان اللہ تعالیٰ کے فضلوں کاوارث ہوتا ہے.اوراس کے نشانات اس کی تائید میں دکھائے جاتے ہیں.اگر یہ جھوٹاہوتا تواس پر چلنے
Page 204
والوں کے لئے اس قدربشارات کے سامان کو ن پیداکرسکتاتھا.جھوٹ بولنے والا دعویٰ توکرسکتاہے مگران دعوئوں کے پوراکرنے کے سامان توپیدا نہیں کرسکتا.غرض چاردلائل اس آیت میں ان کے اعتراض کے رد میں بیان کئے ہیں.اوران میں سے ہرایک اکیلا ہی ان کے اعتراض کوتوڑنے کے لئے کافی ہے.وَ لَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ١ؕ اورہم یقیناًجانتے ہیں (کہ )وہ کہتے ہیں (کہ یہ وحی الٰہی نہیں بلکہ)ایک آدمی اسے سکھاتاہے(مگروہ نہیں سمجھتے لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَّ هٰذَا لِسَانٌ کہ) جس شخص کی طرف وہ (اشارہ کرتے اوران کے ذہن اس کی طرف)مائل ہوتے ہیں اس کی زبان اعجمی ہے عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ۰۰۱۰۴ اوریہ (قرآنی زبان توخوب)روشن (کرکے دکھانے والی )عربی زبان ہے.حلّ لُغَات.اَلْبَشَرُاَلْبَشَرُ:اَلْاِنْسَانُ ذَکَرًاوَاُنْثٰی وَاحِدًا اَوْ جَمْعًاوَقَدْیُثَنّٰی کَقَوْلِ الْقُرْاٰنِ: اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا.بَشَرٌ کے معنے ہیں انسان خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث واحد ہویاجمع.بعض اوقات لفظ بشر کاتثنیہ بھی بنایاجاتاہے جیسے قرآن کی آیت اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ میں بَشَرَیْنِ تثنیہ ہے.(اقرب) لِسانٌ لِسَانٌکے معنے ہیں اَلْمِقْوَلُ بولنے کا آلہ (زبان)اَللُّغۃُ.بولی جانے والی زبان.مذکر اور مؤنث ہردو طرح استعمال کرتے ہیں.چنانچہ لِسَانٌ فَصیْحٌ اورلِسَانٌ فَصِیْحۃٌ دونوں طرح بولتے ہیں.(اقرب) یُلْحِدُوْنَ یُلْحِدُوْنَ اَلْحَدَ سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اورلَحَدَ (مجرد اَلْحَدَ)بِلِسَانِہٖ اِلٰی کَذٰاکے معنے ہیں مَالَ.کسی طرف مائل ہوا.اوراَلْحَدَ فُلَانٌ کے معنے ہیں مَالَ عَنِ الْـحَقِّ.حق سے منحرف ہوگیا (مفردات )پس یُلْحِدُوْنَ اِلَیْہِ کے معنے ہوںگے کہ وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں.اَعْجَمِیٌّ اَلْاَعْـجَمُ مَنْ لَایُفْصِحُ وَلَایُبَیِّنُ کَلَامَہٗ وَ اِنْ کَانَ مِنَ الْعَرَبِ.وہ شخص جو اپنے مافی الضمیر کواچھی طرح واضح نہ کرسکے خواہ وہ عرب ہی کیوں نہ ہو.مَنْ لَیْسَ بِعَرَبِیٍّ وَاِنْ اَفْصَحَ بِالْعَجَمِیَّۃِ وہ شخص جو
Page 205
عرب نہ ہو اگرچہ وہ عجمی یعنی غیر عربی زبان فصیح بولتاہو.(اقرب) تفسیر.کفار کے اس اعتراض کا جواب کہ کوئی بشر آنحضرت ؐ کو سکھاتا ہے اس آیت میں کفار کاایک اوراعتراض بیان کیا گیا ہے جوآج تک مسلمانوں اور مسیحیوں کامحلِ نزاع بناہواہے.میں آیت کامفہوم بیان کرنے سے پہلے اس اعتراض کی حقیقت بیان کرتاہوں.جیساکہ آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے اس میں کفار کا یہ اعتراض بیان کیاگیاہے کہ محمد رسو ل اللہ پر الہام نہیں ہوتا بلکہ ان کو ایک آدمی یہ باتیں سکھاتاہے.گوقرآن کریم نے اس شخص کانام نہیں بتایا.لیکن عبارت سے ظاہر ہے کہ کفار کااعتراض اس موقعہ پر یہ نہ تھا کہ اسے کوئی نامعلوم شخص سکھاتاہے بلکہ اس موقعہ پر ان کا اعتراض کسی خاص شخص کے متعلق تھا جس کا وہ اپنے پروپیگنڈامیں نام بھی بتاتے تھے.قرآ ن کریم نے گواس کی شخصیت کا اظہار نہیں کیا.مگریہ بتایا ہے کہ جس شخص پر وہ اعتراض کرتے تھے وہ اعجمی تھا اوراسی بنا پر ان کے اعتراض کوردّکیا ہے اورتوجہ دلائی ہے کہ ایک اعجمی کی مددسے یہ کتاب جو عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ زبان میں ہے کیونکر تیار ہوسکتی تھی.مفسرین نے اس اعتراض کے متعلق مختلف واقعات بیان کئے ہیں.ایک روایت یہ ہے کہ جویطب بن عبدالعزّٰی کاایک غلام جس کانام عائش یایعیش تھا وہ پہلی کتب پڑھاکرتاتھا اوراسلام لے آیا تھا اوراسلام پر مضبوطی سے قائم رہاتھا.مکہ کے لوگ اس کی نسبت الزام لگاتے تھے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے (روح المعانی زیر آیت ھٰذا).فراءؔ اورزجاجؔکایہی قول ہے اورمقاتلؔ اورابن جبیرکاقول ہے کہ مکہ کے لوگ ابو فکیہ پر الزام لگایاکرتے تھے کہ وہ محمد(صلی اللہ علیہ وسلم)کوسکھاتاہے.(روح المعانی زیر آیت ھذا) بعض نے کہا ہے کہ ابوفکیہ کانام یسارؔتھا اوروہ مکہ کی ایک عورت کاغلام تھا اوریہودی تھا.بیہقی اورآدم بن ابی ا یاس نے عبداللہ بن مسلم الحضرمی سے روایت کی ہے کہ وہ کہاکرتے تھے کہ ہمارے دونصرانی غلا م تھے وہ عین التمر کے رہنے والے تھے.ان میں سے ایک کانام یساراور دوسرے کانام جبرتھا.دونوں مکہ میں تلواریں بنایاکرتے تھے اورکام کرتے وقت انجیل بھی پڑھتے تھے.رسول کریم بازار سے گزرتے ہوئے ان کو انجیل پڑھتے ہوئے دیکھ کر کچھ دیر کے لئے وہاں ٹھیر جاتے.(فتح البیان زیر آیت ھذا نیزروح المعانی زیر آیت ھذا) ایک روایت میں ہے کہ ان میں سے ایک سے لوگوں نے پوچھا کہ اِنَّکَ تُعَلِّمُ مُحَمَّدًا.کیاتم محمدؐ کوسکھاتے ہو؟فقالَ لَا بَلْ ھُوَ یُعَلِّمُنِیْ.اس نے کہا نہیں بلکہ محمدؐ مجھے سکھاتے ہیں.(روح المعانی زیر آیت ھذا)
Page 206
ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ ایک عجمی رومی غلام مکہ میں تھا اس کانام بلعام تھا.رسول اللہ اسے اسلام سکھایاکرتے تھے.اس پر قریش کہنے لگے کہ یہ محمدؐ کوسکھاتاہے.(روح المعانی زیر آیت ھذا) علاوہ ازیں علامہ سیوطیؒلکھتے ہیں کہ قیسؔ ایک عیسائی غلام تھا اس کی ملاقات رسول اللہ سے تھی.اس پر الزام لگائے گئے تھے کہ وہ محمدؐ کوسکھاتاہے.(قرآن العظیم از جلال الدین سیوطی زیر آیت ھذا) درمنثورمیں لکھا ہے کہ عدسؔایک غلام تھا جواوسہ بن ربیع کاغلام تھا اس کی نسبت الزام لگایا جاتاتھا.اور روح المعانی (جلد۱۴ ) اورکشاف میں لکھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار سلمانؓ فارسی کے متعلق الزام لگایاکرتے تھے.ڈاکٹر سیلؔ لکھتاہے کہ ڈاکٹر پریڈیاؔنے سوانح محمدؐ میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن سلام کے متعلق لو گ اعتراض کیاکرتے تھے جس کانام یہودیوں میں عبدیاؔبن سلوم تھا.لیکن خود سیل ؔنے ہی اس کارد کیا ہے.وہ لکھتاہے کہ پریڈیا نے عبداللہ بن سلام کے متعلق غلطی کھائی ہے.سلمان کا نام ا س نے غلطی سے عبداللہ ابن سلام سمجھ لیا ہے.(یعنی دراصل جس کانام لیا جاتاتھا وہ سلمان تھے ) سیل ؔ کہتاہے کہ عام خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسطوری پادری سے جس کانام سرگِیس تھا مددلی تھی.اورخیال کیا جاتاہے کہ سرگیس بحیرہ راہب کانام تھا.جس سے محمدؐصاحب جبکہ آپ حضرت خدیجہؓ کی طرف سے تجارت کے لئے شام کوگئے تھے ملے تھے.اس کی سند میں مشہورمصنف المسعودی کو پیش کیا جاتا ہے جس نے لکھاہے کہ بحیرہ راہب کانام عیسائیوں کی کتاب میں سرگِیس آتاہے.(تفسیر القرآن از پادری ویری زیر آیت ھٰذا) آنحضرت ؐ کو کسی بشر کے سکھانے کے متعلق پادریوں کی غلط آراء پادری ویری ؔمختلف روایات بیان کرکے اپنی رائے کو یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ناموں میں خواہ کتناہی اختلاف ہو لیکن یہ بات ہم کو یقینی طور پر معلوم ہوجاتی ہے کہ محمد(صلی اللہ علیہ وسلم )صاحب کے پاس ایسے ذرائع موجود تھے کہ ہجرت سے پہلے یہودیوں اورعیسائیوں کی مدد حاصل کرسکتے تھے.اوریہ بات کہ وہ اس مدد سے فائدہ حاصل کیا کرتے تھے اس کاناقابل تردید ثبوت مکی زندگی کے آخری دورکی سورتوں میں جن میں یہودیوں اور مسیحیوں کی کتب کی کہانیاں بیان ہیںمہیا ہے.پھر یہی صاحب آیت زیربحث کاحوالہ دےکر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صاحبؐ کے ہمسائے غیر مذاہب کے لوگوں سے مدد حاصل کرنے کا الزام ان پر لگایا کرتے تھے اوراس اعتراض کاجوجواب قرآن نے دیا وہ محمد صاحبؐ کی پوزیشن کی کمزوری کوثابت کررہا ہے.چنانچہ آرنلڈ صاحب بھی اس بارہ میں لکھتے ہیں کہ اس بات کوتسلیم کرتے ہوئے کہ وہ غیرملکی تھے.ہم کہتے ہیں کہ وہ انہیں مسالاتومہیاکرکے دے سکتے تھے.
Page 207
آگے ویر ی کہتا ہے کہ یہی توہے جو وہ کیاکرتے تھے اوراسی وجہ سے کہ محمد صاحب اس مسالے کولے کر اوراپنی نبوت کے مقصد کی تائید میں ڈھال کر خدا(تعالیٰ)کی طر ف منسوب کرکے ان واقعات کو دہرادیاکرتے تھے اورجبرائیل فرشتہ کی وحی اس کو بتاتے تھے.ہم ا س پرانے الزام کو دہرانے میں ہچکچاتے نہیں کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولاکرتے تھے (تفسیر القرآن از پادری ویری زیر آیت ھٰذا)(نَعُوْذُ بِاللہِ مِنْ ہٰذِہِ الْخُرَافَاتِ) آیتيُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ کا اصل مفہوم مسلمان مفسروں اورعیسائی مؤرخو ں اورپادریوں کے خیالات تحریر کرنے کے بعد اب میں اس آیت کامفہو م بیان کرتاہوں.آیت زیر بحث سے معلوم ہوتاہے کہ بعض لو گ اعتراض کیاکرتے تھے کہ رسول کریم ؐ کو قرآن کامضمون کوئی انسان سکھا تا ہے.اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتاہے کہ ان کی زبان تواعجمی ہے اوریہ کلام توعربی میں ہے.مسیحی کہتے ہیں کہ یہ جوا ب غلط ہے کیونکہ معترض یہ نہیں کہتا کہ وہ غلام قرآن کامضمون عربی زبان میں بناکرآپ کو دےدیاکرتے تھے.بلکہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہودی کتب کے مضامین آپ کو بتاتے تھے اورآپ ان مضامین کو اپنی عبارت میں ڈھال لیاکرتے تھے.میرے نزدیک کسی کے کلام کو سمجھنے سے پہلے اس کی عام حالت کاجائزہ لینابھی ضروری ہوتاہے.اگر قرآن کے دوسرے جوابات جووہ مخالفوں کے اعتراضوں کے دیتاہے ایسے ہی بیہودہ ہوتے ہیں جیساکہ یہ جواب ہے جوپادری ویری ؔ اورآرنلڈ صاحب نے قرآن کریم کی طرف منسوب کیا ہے توبے شک ان کی یہ تنقید قابل اعتناء ہوسکتی ہے.لیکن اگراس کے برخلاف قرآن اپنے مخالفوں کے اعتراضا ت کے مناسب اورمدلل جواب دیتاہے.توپھر ا س امر کے تسلیم کرنے کے سواکوئی چارہ نہیں کہ یاتوپادری صاحبان نے سوال نہیں سمجھا یاجواب نہیں سمجھا.دوسراقابل غورامر اس بارہ میں یہ ہے کہ اگریہ جواب ایسا ہی بے جو ڑ تھا جیسا کہ میسرز ویری اورآرنلڈ ظاہر کرنا چاہتے ہیں توکیوں مکہ والوں نے اس کوردّ نہ کیا ؟ اگر ان کاوہی اعتراض تھا جومیسرز ویر ی اورآرنلڈ نے سمجھا ہے توانہوں نے کیوں اس کے جواب میں یہ بات نہ کہی کہ ہماراتویہ اعتراض نہیں کہ آپ عربی اس یہودی یا عیسائی غلام سے بنواتے ہیں.ہم تویہ کہتے ہیں کہ آپ مسالہ اس سے لیتے ہیں.اورپھراپنی زبان میں اس کے مضامین کوبیان کردیتے ہیں.کفار کی طرف سے یہ اعتراض کسی کمزورروایت میں بھی نہیں پایاجاتا.یہ بھی نہیں کہاجاسکتا کہ شاید مسلمانوں نے وہ اعتراض تاریخ میں نقل نہ کیا ہو.کیونکہ جب بیسیوں روائیتیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یااسلام پر زد پڑتی ہے.کتب احادیث میں درج ہیں.تواس ایک اعتراض کے نقل کرنے میں ان کے لئے کیا روک تھی ؟ پس صاف ظاہر ہے کہ کفار نے اس امر کو تسلیم کرلیا تھا کہ ان کے سوال کوٹھیک طورپر سمجھ لیا گیا ہے او ر جواب
Page 208
اس کے مطابق ہی دیاگیاہے.اعجمی کے معنی غیر عرب کے اب یہ سوال رہ جاتاہے کہ مذکورہ سوال کا جواب جو قرآن کریم نے دیاہے اس کا کیا مطلب ہے ؟تواس کامطلب سمجھنے سے پہلے اَعْجَمِیٌّ کے معنے سمجھ لینے ضروری ہیں.عربی زبان میں عرب اورعجم دولفظ عربوںاورغیر عربوں کے لئے مستعمل ہوتے ہیں.اوراسی مادہ سے اَعْجَمٌ کالفظ ہے جوغیر عر ب کے لئے بولاجاتاہے.چنانچہ تاج العروس جلد۸میں ہے.عرب کہتے ہیں رَجُلٌ اَعجمُ وَقَوْمٌ اَعْجَمُ.وہ شخص اعجم ہے یا وہ قو م اعجم ہے.مطلب یہ کہ وہ آدمی یاقوم غیر عر ب ہے.عربوں میں سے نہیں ہے.اعجمی کے معنے اس حد تک کے حوالہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اعجم غیرعرب کے معنوں میں استعمال ہوتاہے.لیکن اس کے سوااعجم کے معنے مَنْ لایُفْصِحُ کے بھی ہیں یعنی وہ شخص جو بات کھو ل کر نہ بیا ن کرسکے.اسی طرح یہی معنے اعجمی کے بھی ہیں.(تاج)اوران معنوں میں عرب کی نسبت بھی یہ لفظ بولاجاسکتاہے.اسی طرح اعجم اس شخص کی نسبت بھی بولتے ہیں جس کی زبان میں لکنت ہو خواہ وہ فصیح الکلام ہی کیوں نہ ہو.(تاج) اعجمی لفظ کا استعمال زبان کے لئے ان معانی کو بیان کرنے کے بعد اب میں اس طرف توجہ پھیرناچاہتاہوں کہ ا س جگہ اعجمی کالفظ انسان کی نسبت نہیں بولاگیا بلکہ زبان کی نسبت بولاگیا ہے.یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جس کی نسبت قرآن بنانے میں مدد دینے کاالزام لگایا گیا ہے وہ اعجمی ہے.بلکہ یو ں فرمایا ہے کہ جس شخص کی نسبت یہ لوگ ایسا گمان کررہے ہیں اس کی زبان اعجمی ہے یعنی(۱)غیر عر ب لوگوں کی زبان ہے یا(۲)یہ کہ اس کی زبان ایسی ناقص ہے کہ وہ اپنامطلب بیان ہی نہیں کرسکتا.اَعْجَمِیٌّ کے ایک معنے لکنت کے بھی ہیںوہ معنے بولی کی نسبت استعمال نہیں ہوسکتے.کیونکہ لکنت چمڑے کی زبان میں ہوتی ہے.الفاظ سے مرکب بولی میں لکنت نہیں ہواکرتی.پس جب اعجمی کا لفظ زبان کی نسبت بولاجائے توا س کے دومعنے ہوتے ہیں.غیر عرب زبان یعنی جسے اعجم لوگ بولتے ہیں.یاپھر اس حد تک غیر فصیح زبان جو مطلب واضح نہ کرسکتی ہو خواہ اس کابولنے والاعرب ہی کیو ں نہ ہو.اورخواہ وہ عربی میں ہی کیوں بات نہ کررہا ہو.آیت کے دو معنی اعجمی زبان کے معنوں کی تعیین کرنے کے بعد اب میں یہ بتاتاہوں کہ ان دونوں معنوں کو مدنظررکھ کر اس آیت کے یہ دومعنے ہوتے ہیں.(۱)یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو قرآن کوئی دوسراشخص سکھاتاہے.وہ شخص جس کی طرف یہ لوگ اس کام کو منسوب کرتے ہیں ا س کی زبان توغیر عربی ہے.
Page 209
(۲)جس کی نسبت یہ لوگ اس کام کو منسوب کرتے ہیں وہ تواپنے خیالات اداکرنے پر قادرہی نہیں اورقرآن کی زبان عربی ہے.اورعربی بھی وہ کہ مضمون اس میں سے پھوٹ پڑتے ہیں.ان دونوں جوابوں کودیکھ لو کہ نہایت معقول اورمدلل اور مسکت ہیں.جوعربی نہ جانتاہووہ بھی عر ب کو کچھ سکھانہیں سکتا.اورجس کی دماغی حالت ایسی کمزورہوکہ صحیح طورپر با ت نہ کرسکتاہو وہ بھی کوئی علمی بات کسی کو نہیں بتاسکتا.آنحضرت ؐ پر عیسائی غلام سے سیکھنے کا اعتراض اور اس کا جواب اب میںیہ بتاتاہوں کہ کفار کس شخص کی طرف اشارہ کرتے تھے.اس غلام کے مختلف نام آتے ہیں.مگر ان مختلف ناموں میں سے اس جگہ کے مطابق وہی روایت ہے جس میں جبر کی نسبت سکھانے کاشبہ ظاہر کیا گیا ہے.کیونکہ باقی غلام جن کے نام لئے گئے ہیں کھلے طورپر مسلما ن تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح شام ملتے رہتے تھے.ان میں کسی ایک کو اعتراضات کا نشانہ بنانے کی کوئی وجہ نہ تھی.اگراعتراض ہوتاتوسب پرہو تا.وہ شخص جو اکیلا تھا اور جس کی نسبت کفار کو شبہ ہوتاتھا کہ شاید یہ باتیں سکھاتاہے وہ جبر ہی ہے جو بہت دیر بعد مسلمان ہواہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں نہیں آتاتھا بلکہ جیساکہ روایات سے ثابت ہے آپ بعض دفعہ اس کے پاس جبکہ وہ تلواریں بناتے ہوئے انجیل کی آیات پڑھاکرتاتھا کھڑے ہوجاتے تھے.پس اس آیت میں جس شخص کی طرف اشارہ ہے وہ یہی شخص ہے اورجیساکہ حالا ت سے معلوم ہوتاہے کہ یہ شخص اپنے مذہبی جو ش کی وجہ سے لوہاکوٹتے ہوئے انجیل پڑھتاجاتاتھا اوربوجہ غیر زبان ہونے کے عجوبہ خیال کرتے ہوئے لوگ ا س کے گرد جمع ہوجاتے تھے.رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جوش سے متاثر ہوتے اورآپ بھی بعض دفعہ اس کے پاس کھڑے ہوجاتے اوریہ خیال کرکے کہ جس شخص میں مذہب کااس قدر جوش ہے وہ ضرور سنجیدگی سے دینی مسائل پرغورکرے گااسے اسلام کی تلقین کرتے.بعض لوگ جنہوں نے اس کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے دیکھا انہوں نے یہ مشہورکردیا کہ وہ آپ کو سکھاتاہے.چنانچہ اوپر جو احادیث نقل ہو ئی ہیں ان میں یہ بھی آتاہے کہ اس سے یا اس کاجوایک اورساتھی تھا اس سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ کیاتم محمد(صلی اللہ علیہ وسلم ) کواپنے دین کی باتیں سکھاتے ہو؟تواس نے کہا کہ نہیں وہ مجھے سکھاتے ہیں.(روح المعانی زیر آیت ھٰذا) اس سوال و جواب سے ظاہر ہے کہ لوگ اسی کی نسبت گمان کرتے تھے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتاہے.اس الزام کا جواب قرآن کریم نے یہ دیاہے کہ اس کی زبان تواعجمی ہے یعنی وہ عربی زبان نہیں
Page 210
جانتایاایسی تھوڑی جانتا ہے جسے زبان جاننانہیں کہہ سکتے.اورقرآن کی زبان تو عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ ہے پھر بتائوکہ ان دونوں کے درمیان تبادلہ خیال کس طرح ہوتاہے.آخر مذہب کی تعلیمات سکھانے کے لئے زبان ہی ذریعہ ہے اگردونوں شخصوں کی زبان ایک نہیں.ایک کی زبان غیر عربی ہے اور دوسرے کی عربی.توعربی دان غیر عربی دان سے کس ذریعہ سے فائدہ اٹھاسکتاہے.یہ جوا ب نہایت معقول ہے اوراس جواب کو کوئی غیر معقول نہیں کہہ سکتا.دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہوسکتے تھے کہ اس کی زبان جس کی نسبت اتہام لگایاجاتاہے کہ وہ سکھاتاہے گوعربی ہو.مگروہ اپنا مفہوم اداکرنے کی قابلیت نہیں رکھتا.اگر یہ معنے کئے جائیں تب بھی جواب درست ہے.کیونکہ جواب میں قرآن کریم کو پیش کیاگیا ہے اوربتایاگیا ہے کہ قرآن کی زبان اس قدروسیع مطالب پر مشتمل ہے کہ وہ مبین کہلانے کی مستحق ہے یعنی وہ ہراعتراض کاخود ہی جواب بھی دیتی جاتی ہے.پھریہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنا مطلب بھی پوری طرح واضح نہیں کرسکتا یعنی موٹی عقل والااورکُند ذہن ہے.وہ ایسے مطالب محمد رسول اللہ کوبتائے کہ ہردعویٰ کے ساتھ اس کی دلیل بھی موجود ہو.اورہرمشکل جو قرآن پڑھتے ہوئے انسانی ذہن پیداکرے اس کاحل بھی ساتھ ہی موجود ہو.جوشخص کسی علمی بات کے بیان کرنے کے قابل نہیں اورموٹی عقل کاآدمی ہے اوراپنے مطلب کو واضح نہیں کرسکتا وہ اس قسم کی باتیں سمجھا ہی کس طرح سکتا ہے.یہ دلیل بھی ایسی کامل اورمُسکت ہے کہ ا س کے معقول اورلاجواب ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں کیاجاسکتا.ممکن ہے کو ئی اعتراض کرے کہ ہوسکتاتھا کہ وہ غلام اپنے بھدّے پیرایہ میں اناجیل کے واقعات سنادیتاہو.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں بیان کردیتے ہوں.اس کا جواب یہ ہے کہ مبین کالفظ اس سوال کا جواب بھی دے رہاہے.کیونکہ بتانے والا اگرنامکمل سچائیاں بتاتا تھاتوکونسی صورت تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبین صداقتوں یعنی ان صداقتوں میں جو اپنی سچائی کی آپ ہی دلیل ہوں تبدیل کرسکتے تھے کیاکوئی شخص یہ طاقت رکھتاہے کہ جھو ٹ یاغلط بات کو صرف مدلل ہی نہیں بلکہ ایسا مدلل بنادے کہ مضمون روزروشن کی طرح کھل جائے.بعض مسیحی اعتراض کویہ رنگ دیتے ہیں کہ قرآن کایہ دعویٰ ہے کہ اس میں چونکہ یہود و نصاریٰ کی کتب کی باتیں ہیں اورمحمدؐرسول اللہ بوجہ امّی ہونے کے خود ان باتوں سے واقف نہیں ہوسکتے تھے.اس لئے ثابت ہواکہ یہ باتیں انہوں نے خدا تعالیٰ سے معلو م کر کے دنیاکو بتائی ہیں.اس دعویٰ کے خلاف یہ اعتراض ہے کہ وہ بعض مسیحی غلاموں سے غلط اوربے جوڑ روایات سن کر قرآن میں داخل کرلیتے تھے.اوراس صورت میں یہ ضروری نہیں کہ جس شخص سے
Page 211
وہ ان قصوں کو سنیں وہ ضرور بڑے دماغ کااوربڑی سمجھ کا آدمی ہو.بلکہ واقعات چونکہ غلط بیان ہوئے ہیںاس لئے جاہل اوراکھڑ غلام کی نسبت ایسا الزا م کے واقعا ت زیادہ مطابق بیٹھتا ہے نہ کہ اعترا ض کو دور کرتا ہے.قرآن مجید اپنے اندر جملہ کتب کی صداقتیں رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں کہیں وہ دعویٰ بیان نہیں جومسیحی قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں.قرآن کریم اپنی سچائی کی یہ دلیل نہیں دیتا کہ چونکہ اس میں اہل کتاب کی کتب کی باتیں بیان ہوئی ہیں و ہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے.بلکہ قرآن تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں وہ صداقتیں موجود ہیں جواہل کتا ب کی کتب میں نہیں ہیں اس لئے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے.چنانچہ اسی سورئہ نحل میں یہ آیات گذر چکی ہیں کہ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.وَ مَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.(النحل :۶۴،۶۵)یعنی ہمیں اپنی ہی ذات کی قسم ہے کہ تجھ سے پہلے ہرقوم میں نبی گزرچکے ہیں.اورہرقوم کے پاس ہدایت نامہ آچکا ہے مگرباوجود اس کے شیطان نے ان قوموں کو گمراہ کردیا اوراب وہ مختلف باتیں اپنے مذہب کی طر ف منسوب کررہے ہیں جوخدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوئی تھیں اوروہ اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرشیطان کے تصرف میں آئے ہوئے ہیں اوردردناک عذاب کا موردبننے کے خطرہ میں ہیں.پس ان کے ان اختلافات کے مٹانے کے لئے ہم نے تجھ پر یہ کتاب اتاری ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے وہ سچائیاں جوان سے مخفی ہوچکی ہیں اوروہ ان کے متعلق اختلاف کررہے ہیں بیا ن کرے.اوراس قرآن کے ذریعہ سے ہم نے مومنوں کے لئے ہدایت اوررحمت کے سامان پیداکئے ہیں.اس آیت میں پہلے سب قوموں میں نبی آنے کا ذکر ہے اوربعد میں قرآن کریم کے نزول کا.اوریہ نہیں فرمایا کہ چونکہ یہ پہلے نبیوں کی کتب کی باتیں بیان کرتا ہے اس لئے سچا ہے.بلکہ یہ فرمایا ہے کہ پہلی کتب کو لو گوں نے چھوڑ دیا اورشیطان کے پیچھے چل پڑے اوران میں قسم قسم کے اختلاف پیداہوگئے.یہ قرآن ان اختلافوں کو مٹانے اورجو صداقت مخفی ہوگئی تھی اسے ظاہرکرنے کے لئے آیا ہے.قرآن کریم کے اس دعوے کی موجودگی میں یہ کہنا کہ محمدرسول اللہ محض پچھلی کتب کی باتیں بیان کرکے جن کو وہ چند غلاموں سے سن لیتے تھے اپنی سچا ئی کادعویٰ کرتے تھے کس قدرغلط ہے.خود یہ آیت بھی تو جیساکہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں یہی بات پیش کررہی ہے.کہ قرآن کریم کی برتری کسی نقل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے مبین ہونے کی وجہ سے ہے.اورمُبِیْن ہونے کے لئے وسیع اورمخفی علوم کی ضرورت
Page 212
ہے.جن کی اس آدمی سے جس کی طر ف یہ کلام منسوب کیاجاتا ہے توکیا امید کی جاسکتی ہے بڑے سے بڑا عقلمند انسان بھی اس کتاب کے بنانے میں مدد نہیں دے سکتا جس میں سب سچائیا ںبادلیل بیان کی گئی ہوں.اورسب اعتراضوں کا رد موجود ہو.ایسی کتاب تو صرف خدا تعالیٰ ہی اتارسکتا ہے.ممکن ہے کو ئی یہ کہے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ غلام جاہل تھے.ہم توسمجھتے ہیں کہ کوئی بڑاعالم رسول کریم (صلی اللہ علیہ وسلم)کے قبضہ میں آگیاتھا.جن مسیحیوں نے اس آیت کا مشار الیہ سرگِیس کوقرار دیا ہے اسی حکمت سے قرار دیا ہے کیونکہ وہ زیادہ عقلمند تھے.اورانہوں نے اس امر کو محسوس کرلیاتھا کہ قرآن کریم میں یہود ونصاریٰ اوراسلام کے درمیان اختلافی امورکی جو بحث ہے و ہ غلام توالگ رہا اچھے لکھے پڑھے عیسائی کی دسترس سے بھی باہر ہے.اس لئے انہوں نے ایک فرضی سرگیس کو تجویز کیا کہ وہ ایک نُسطوری راہب تھا اورآپ کو سکھایاکرتاتھا.تاریخی طورپر تو خود مسیحی مصنفوں نے ہی ان کی بات کو رد کردیا ہے.عیسائیوں کے اعتراض کا عقلی ردّ مگرمیں عقلی طورپر بھی اس کا ایک جواب بیان کردیتاہوں اوروہ یہ ہے کہ اگرنصاریٰ اس الزام کو یہ شکل دیں تو پھر بھی انہی کے مذہب پر زدپڑتی ہے کیونکہ اس کے یہ معنے ہوں گے کہ یہود و نصاریٰ کی جوتصویر اسلام نے پیش کی ہے خواہ انسانوں سے سیکھ کر کی ہے مگر ہے وہی سچی.اوراگر وہ تصویر سچی ہے توان کے مذاہب کے غلط ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے.اس پہلو کے بدلنے سے صرف ان کویہ تسلی ہوگئی کہ ہمارے مذاہب توجھوٹے ثابت ہوہی گئے ہیںہم نے قرآن پر بھی اعتراض کردیا کہ اسے بھی انسانوں نے بنایا ہے.لیکن یاد رہے کہ شبہ یقین کاقائم مقام نہیں ہوسکتا قرآن کریم کی طرف جو بات و ہ منسوب کررہے ہیں اسے توخود ان کے اپنے آدمی ناقابل قبول قراردیتے ہیں.لیکن یہ تسلیم کرکے کہ قرآن کریم نے یہودیوں اور مسیحیوں سے جہاں جہاں اختلا ف کیا ہے وہ کسی بڑے عالم کی تحقیق ہے.جس نے اہل کتاب کی لائبریریاں چھان کر ان باتوں کو نکالا ہے.اورموجود ہ مذاہب کی غلطیوں کو ظاہرکردیا ہے.اس سے تو ان مذاہب کاکچھ بھی نہیں رہتا.اوریہودی اور مسیحی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ یہودیت وہ نہیں جوموجودہ تورات اورکتب یہود میں موجود ہے بلکہ وہ ہے جوقرآن میں بیان ہوئی ہے.اورنصرانیت وہ نہیں جوموجود ہ اناجیل میں ہے بلکہ وہ ہے جو قرآن میں ہے.اوراگر وہ ایسا کہیں گے تودوسرے لفظوں میں قرآن کریم کی تصدیق کریں گے.اب ایک پہلو آیت کے ترجمہ کارہ گیا ہے جوقابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ کوئی کہہ سکتاہے کہ آیت کایہ ترجمہ کہ جس کی نسبت لو گ گمان کرتے ہیں اس کی زبان غیرعربی ہے.اس کے گوایک معنے یہ بھی ہوسکیں کہ اس کو عربی یاآتی ہی
Page 213
نہیں یااتنی نہیں آتی کہ وہ اپنا مطلب بیان کرسکے.لیکن اس کے یہ معنے بھی توہوسکتے ہیں کہ اس کی مادری زبان غیر عربی ہے.اورایسا شخص جسکی مادری زبان غیر عربی ہو بعد میں عربی سیکھ بھی توسکتاہے پس جواب مکمل نہ ہوا.اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معنے اس آیت کے نہیں ہوسکتے کیونکہ یہ سوال قرآن کریم نے دوسری جگہ خود بیان کیا ہے.اوراس کاالگ جواب دیا ہے.جس سے ثابت ہوتاہے کہ وہ معنے آیت زیر بحث میں نہیں ہیں.نیزاس سے یہ امر بھی ثابت ہوتاہے کہ پادری ویری کایہ استنباط کہ سورۃ نحل کا جواب بالکل بوداہے اوراس سے اعتراض کی سچائی ثابت ہوتی ہے.ان کی ناواقفیت کی وجہ سے ہے کیونکہ جب قرآن کریم نے وہی سوال جو وھیریؔصاحب اور دوسرے مسیحی مصنفوں نے اس آیت سے نکالا ہے سور ۃ فرقان میں خود بیان کیا ہے اوراس کا جواب نہایت زبردست دیا ہے.تویہ کس طر ح ممکن تھا کہ سور ۃ نحل میں اس سوال کانہایت بوداجواب دیاجاتا.سورۃ فرقان خود وھیر ی صاحب کے نزدیک ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے.وہ لکھتے ہیں کہ :.’’اس سورۃ کی آیتیں محمد(صلعم)کی ابتدائی مکی وحی میںسے ہیں.‘‘(تفسیر قرآن از پادری ویری تعارف سورہ فرقان) اورسورۃ نحل کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ :.’’تما م شہادت اندرونی ہویابیرونی ہمیں اس امر کے ماننے پرمجبورکرتی ہے کہ یہ (نحل)آخری مکی سورتوں میں سے ہے.‘‘(تفسیرالقرآن از پادری ویری تعارف سورۃ نحل) اب کیا کو ئی عقلمند تسلیم کرسکتا ہے کہ جس اعتراض کو سورۃ فرقا ن میں نہایت زبردست دلائل کے ساتھ ردکیا ہے اس کے چھ سال کےبعد اس سوال کا جواب سورۃ نحل میں نہایت بودااورکمزوردےدیا ہے.اگرفرقان بعد کی ہوتی توکوئی شبہ بھی کرسکتاتھا کہ اس وقت جواب نہیں سوجھا بعد میں جوا ب بنالیا.مگر فرقان خود مسیحی مصنفوں کے نزدیک پہلے کی ہے اورنحل بعد کی.اب میں مضمون کو یکجا بیان کرنے کے لئے پہلے وہ دلائل بیان کرتاہوں جوسورۃ فرقان میں بیان کئے گئے ہیں.سورۃ فرقان میں آتاہے :.وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكُ ا۟فْتَرٰىهُ وَ اَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ١ۛۚ فَقَدْ جَآءُوْا ظُلْمًا وَّ زُوْرًا.وَ قَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا.قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا(الفرقان :۵ تا ۷) یعنی کفار کہتے ہیں کہ قرآن ایک جھوٹی کتا ب ہے اورمحمد ؐرسول اللہ کواس کے بنانے میں دوسرے لوگ مدد
Page 214
دیتے ہیں.ان کفار نے یہ اعتراض کرکے سخت ظلم کیا ہے اورجھوٹ بولاہے اوروہ اس اعتراض کو پکا کرنے کے لئے یوں دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا.بس پرانے لوگوں کی باتیں نقل کردی گئی ہیں.محمد(صلعم)وہ باتیں لکھوالیتے ہیں اورصبح و شام ان کے سامنے وہ پڑھی جاتی ہیں (تاکہ یاد رہیں) تُوان سے کہہ کہ قرآن کوتوا س نے اتاراہے جوآسمان اورزمین کے رازوںکو جانتا ہے.وہ بہت بخشنے والا اورمہربان ہے.اس آیت میںصاف لفظوں میں اس اعتراض کونقل کیاگیاہے جوویریؔ صاحب سورۃ نحل کی آیت سے نکالنا چاہتے ہیں اوراس اعتراض کو پڑھ کر یہ بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ سورہ نحل والی آیت کااعتراض اس آیت سے مختلف ہے.کیونکہ سورۃ نحل میں ایک شخص کی طرف سکھانا منسوب کیاگیاہے اوریہاں کئی شخصوں کی طرف.پھر سورۃ نحل والی آیت میں گونام نہیں لیاگیامگر یہ ضرو ر بتایاگیا ہے کہ جس پر الزام لگایاجاتاہے وہ معیّن شخص ہے.لیکن سورۃ فرقان میں وہ جماعت غیر معیّن رکھی گئی ہے.اسی طرح سورۃ نحل میں سکھانے کے کام کا وقت نہیں بتایا گیا لیکن سورۃ فرقان میں یہ بھی بتایاگیاہے کہ صبح و شام یہ تعلیم کاسلسلہ جاری رہتاہے.سورۃ فرقان کی آیات کے الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چونکہ صبح و شام نماز کے لئے اورقرآن سیکھنے کے لئے دارارقم میں جمع ہوتے تھے.وہ نادان یہ خیال کرتے تھے کہ شاید اس جگہ جمع ہوکر بعض مسیحی غلام اپنی کتب کی باتیں ان کو بتاتے ہیں یاان سے لکھ کر صحابہ لے آتے ہیں اورپھر و ہ صبح و شام حفظ کی جاتی ہیں.ان جاہلوں کی عقل میںصبح و شام کی نمازیں توآہی نہیں سکتی تھیں.وہ اس اجتماع کو منصوبہ بازی کا وقت سمجھتے تھے.خود مجھے اس بار ہ میں ایک تجربہ ہوچکا ہے جس سے اس قسم کی بدگما نی کی حقیقت خوب معلوم ہوجاتی ہے.کوئی بیس سال کاعرصہ ہوامیں لاہور گیا.مجھ سے آریو ں کے مشہور لیڈر لالہ رام بھجدت جواب فوت ہوچکے ہیں ملنے کے لئے آئے.ان کے ساتھ کچھ اَورصاحبان بھی تھے.جن میں شیر پنجاب جو سکھوں کامشہور اخبار ہے اس کے ایڈیٹر صاحب بھی شامل تھے.اتفاق سے اس دن میرالیکچر تھا.وہ لیکچر سننے کے لئے ٹھیر گئے.مجھے سارادن کام کی وجہ سے حوالے نکالنے کاموقعہ نہیں ملاتھا.اس لئے میں نے حافظ روشن علی صاحب مرحوم کو (اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے)جوآیات کو نکالنے کاخاص ملکہ رکھتے تھے سٹیج پربٹھالیا.اورکہاکہ میں آپ کومضمون بتاتاجایا کروں گا.آپ مجھے آیت کے الفاظ بتاتے جایاکریں.خیر میں نے لیکچر شروع کیا.جہاں کسی آیت سے استدلال کی ضرورت ہوتی.میں آہستہ سے ایک دو لفظ آیت کے پڑھ دیتا یا مضمون بتادیتا اوروہ ساری آیت پڑ ھ دیتے.میں اسے پڑھ کر جو استدلال پیش کرناہوتا تھا اسے بیا ن کردیتا.دوسرے دن شیر پنجاب میں ایک مضمو ن نکلا کہ کل
Page 215
ہم بھی امام جماعت احمد یہ قادیان کے لیکچر میں تھے لیکچر اچھا تھا.مگر ہم نے ذراتجسس کیا اورسٹیج کے پچھلی طرف گئے تومعلوم ہو اکہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک عالم چھپایا ہواتھا.وہ مضمون بتاتاجاتا تھا اورمرزا صاحب دہراتے جاتے تھے.واقف کار لوگوں میں کئی دن اس پر ہنسی اُڑتی رہی اورسردار صاحب سے بھی کسی نے جاذکر کیا وہ بہت شرمندہ ہوئے.اورکہا کہ میں نے توسمجھا تھا کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے راز معلوم کرلیا ہے.ایسی ہی ہوشیار ی مکہ والوں نے دکھائی تھی.کام والے لوگوںکو صبح و شام ہی فرصت مل سکتی تھی.و ہ صبح اورشام کی نمازیں اداکرنے کےلئے اور قرآن پڑھنے کے لئے دارارقم میں جمع ہوجاتے تھے.کفار کے بعض زیادہ عقلمند لوگ خیال کرتے تھے کہ ہم نے را ز معلوم کرلیا ہے.یہ قرآن کی تصنیف کے لئے جمع ہوتے ہیں.(السیرةالنبویۃ لابن ہشام.ذکر من اسلم من الصحابة بدعوة ابی بکر) عقلمند کے لئے ا س میں بھی ایک نشان ہے کیونکہ ا س میں بھی یہ اعتراف پایا جاتا ہے کہ قرآن کوکوئی ایک شخص نہیں بناسکتا.تبھی انہوں نے اس کے بنانے میں مدددینے والی ایک جماعت قراردی.جن میں سے بعض عقلی باتیں جمع کرتے تھے اوربعض پرانی کتب کی تعلیم جمع کرتے تھے.اب میں سورۃ فرقان میں اس اعتراض کے جو جواب دئے گئے ہیںبیان کرتاہوں کفارکے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اس کے دوپہلوئوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے.(۱)اول یہ کہ جن کی نسبت کہاجاتاہے کہ وہ قرآن کریم کے بنانے میں مدددیتے ہیں.کیا وہ ایسا کرسکتے تھے ؟ (۲)دوسرے یہ کہ جس چیز کی نسبت کہا جاتاہے کہ بعض غلاموں نے لکھائی ہے.کیا وہ انسانوں کی لکھائی ہوئی ہوسکتی ہے ؟ پہلے سوال کا جواب قرآن کریم یہ دیتاہے کہ یہ سوال نہایت ظالمانہ اورجھوٹاہے.ا س جواب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن غلاموں کی نسبت کہاجاتاہے کہ و ہ آآکررسول کریمؐ کو قرآن سکھایاکرتے تھے ان کے متعلق دیکھنا چاہیے کہ وہ اسلام کی خاطرکیا کیاتکالیف اٹھارہے تھے.یہ کیونکر ممکن ہوسکتاتھا کہ ایسے لوگ جو خود قرآن بنا بناکر محمدؐ رسول اللہ کو دیتے تھے اس جھوٹے کلام کی خاطر رات اوردن تکلیفیں اٹھارہے تھے.اسلام کی خاطران غلاموں میں سے بعض نے جانیںدیں.بعض کی آنکھیں نکالی گئیں.ایک میا ں بیوی کو اس طرح قتل کیا گیا کہ خاوند کی دونوں لاتوں کو دواونٹوں سے باندھ کر دوطر ف چلادیا.اوراس کی بیوی کی شرمگاہ میں نیزہ مارکر اس کے سامنے قتل کیا.اوران کے لڑکے کو بھی سخت ایذائیں دیں.اس دوران میں انہیں بار بار کہاجاتاتھا کہ محمدرسول اللہ
Page 216
کاانکا رکردیں توچھو ڑ دئے جائیں گے.مگر میاں بیوی مرتے مرگئے پرصداقت کادامن ہاتھ سے نہ چھوڑا(الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ ذکر سمیّۃ بنت خباط).یہ آزادوں کاسردار نام نہاد غلام یاسربھی انہی غلاموں میں سے تھا جن کے متعلق یہ اتہام لگایاجاتاتھا کہ و ہ محمد رسول اللہ ؐ کوسکھاتے ہیں.کیاکوئی انسان مان سکتاہے کہ خود ہی قرآن بناکر دینے والے محمدؐ رسول اللہ کے نام پر ایسے ایسے عذاب اٹھاکر جانیں قربان کررہے تھے.مکہ کے کافر تووقتی جوش میں اندھے ہو رہے تھے کیاآج کل کی عیسائی دنیا میں بھی کو ئی دیکھنے والی آنکھ نہیں ؟ کوئی بولنے والی زبان نہیں جواس بار با دہرائے جانے والے ظالما نہ اورجھوٹے اعتراض کے خلا ف آواز اٹھائے ؟ اعتراض کادوسراپہلویہ ہے کہ کیا وہ کلام ان غلاموں کاسکھایاہواہو سکتا ہے؟اس کا جواب یہ دیاہے کہ جنہیں تم قصے کہتے ہو وہ قصے ہیں ہی نہیں بلکہ پیشگوئیاں ہیں.ان کااتارنے والاتوآسمانو ںاورزمین کے غیبوں کاجاننے والا خداہے.یعنی ان میں آئند ہ کے حالات بیان کئے گئے ہیں نہ کہ پرانے واقعات.اورانسان آئندہ کے حالات نہیں جان سکتا.اورنہ بتاسکتاہے.اب دیکھو تویہ جواب کیساواضح اورصحیح ہے.آنحضرت کا جبرغلام سے انجیل سیکھنا غلط ہے غرض سورئہ نحل میں یہ اعتراض نہیں کہ دوسراکوئی شخص اسے مضمو ن سکھاتاہے.وہ اعتراض فرقا ن میں بیان ہواہے اوراس کاایسا دندان شکن جواب دیا گیاہے کہ شریف آدمی اسے سن کر پھر اس اعتراض کو نہیںدوہرا سکتا.اورسورۃ نحل میں وہ اعتراض نہیں بلکہ یہ اعتراض بیان ہواہے کہ فلاں غلام قرآن سکھاتاہے.حالانکہ وہ غلام عربی نہیں جانتا تھا.صر ف کچھ آیات انجیل کی جو غالباً یونانی زبان میں ہوں گی کام کرتے وقت پڑھاکرتا تھا.محمد رسول اللہ اس کے جوش کو دیکھ کر اس کے پاس تبلیغ کے لئے ٹھیر جاتے تھے کہ کوئی بات اس کے کان میں پڑ جائے توشاید کسی وقت ہدایت کاموجب بنے تبھی اس نے خو د اقرار کیا ہے کہ یہ مجھے سکھاتے ہیں.اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ اسے توعربی بولنی اس قدر نہیں آتی کہ کوئی علمی مضمون بیا ن کرسکے.یہ اتنی ہی مدد کرسکتا ہے کہ انجیل کی عبارتیں عبرانی یایونانی زبانوںمیں آپ کویاد کراد ے.لیکن اگر ایساہوتا توقرآن کاایک حصہ عبرانی یایونانی ہوتا.مگرقرآن توساراعربی میں ہے.پھر جبکہ ترجمانی وہ غلام نہیں کرسکتا اورعبرانی یونانی کی عبارتیں قرآن میں موجود نہیں توسکھایا کس نے اورسیکھا کس نے ؟اس سے زبردست جواب اور کیاہو سکتا ہے اوراسے بوداکہنے والے کو سوائے متعصب یاموٹی عقل والے کے اور کیا کہہ سکتے ہیں.آنحضرت پر جبر غلام سے سیکھنے کا اعتراض یہ بھی یاد رہے کہ روایت میں دوغلاموں کا ذکر آتاہے لیکن میں نے ایک غلام کا ذکر کیا ہے.اس کی دووجہیں ہیں.ایک یہ کہ قرآن کریم کی آیت سے ظاہرہوتاہے کہ وہ ایک
Page 217
غلام کے متعلق اعتراض کیا کرتے تھے.دوسرے ایک روایت جس میں ذکر ہے کہ اس شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ کیاتومحمد(صلعم)کوسکھاتا ہے ؟تواس نے کہاکہ نہیں.اس میں بھی ایک ہی آدمی کا ذکر ہے.پس خواہ دوغلام ہی اس جگہ اکٹھے کام کرتے ہوں پرشبہ معلوم ہوتاہے کہ ایک ہی کے متعلق کیاجاتا تھا.آنحضرت ؐ کے زمانہ میں انجیل کا عربی ترجمہ نہ ہواتھا اس جگہ ایک اورسوال بھی غورطلب ہے جواس اعتراض کے متعلق ہماری صحیح راہنمائی کرسکتاہے.اوروہ یہ ہے کہ کیا اس وقت تورات اور انجیل کے عربی تراجم ہوچکے تھے اوروہ اس قدررائج تھے کہ غلام بھی ان کو کام کے وقت پڑھاکرتے تھے ؟کیونکہ اگریہ صورت نہ ہوتوعبرانی اور یونانی کتب کی عبارتوں سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ اٹھاسکتے تھے اورنہ وہ غلام خود ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے.کیونکہ عبداللہ بن سلام کے سواکسی ایک مسلمان کے متعلق بھی تاریخ سے ثابت نہیں کہ وہ عبرانی جانتا تھا(مسلم کتاب الحدودباب رجم الیہود اھل الذمة فی الزنی ) اوریونانی سے واقف کاتوتاریخ میں میرے علم میں کوئی ذکر ہی نہیں آتا.جہاں تک میری تحقیق ہے اس وقت تک عربی زبان میں تورات اور انجیل کے تراجم نہیں ہوئے تھے.اورجب ان کتب کے تراجم نہیں ہوئے توطالمود وغیرہ جو یہود کی روایتوں کی کتب ہیں ان کے تراجم کس نے کرنے تھے.میرے اس خیال کی تائید مندرجہ ذیل دلائل سے ہوتی ہے.انجیل کے تراجم کا رواج چودھویں عیسوی سے ہوا (۱)اس وقت تک انجیل کے تراجم کا رواج ہی نہ تھا.تراجم کارواج تیرھویں چودہویں صدی سے شروع ہوا.اوریہی وجہ ہے کہ ہمارے مفسرین جنہوں نے تفسیر میں مددلینے کے لئے ہرقسم کے علوم پڑھ ڈالے تھے جب تورات اور انجیل کے حوالے دینے بیٹھتے ہیں توبالکل بے ثبوت کہا نیاں ان کی طرف منسوب کردیتے ہیں.جن کانام و نشان بھی بائبل میں نہیں ہے جس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو عربی کی انجیل میسر نہ تھی.اگرعربی میں تورات اور انجیل ہوتی توکیایونان کا فلسفہ اورحکمت پڑھنے والے ان کتب کو نہ پڑھتے ؟ آنحضرت ؐ کے زمانہ میں انجیل یونانی یاعبرانی میں تھی (۲)اسلامی روایات سے بھی یہی معلوم ہوتاہے کہ اس وقت اناجیل یونانی یا عبرانی زبان میں ہی تھیں.بخاری باب بدء الوحی میں ورقہ بن نوفل کے متعلق لکھاہےقَدْ تَنَصَّرَ فِی الْجَاھِلِیَّۃِ وَکَانَ یَکْتُبُ الْکِتَابَ الْعِبْرَانِیَّ فَیَکْتُبُ مِنَ الْاِنْجِیْلِ بِالْعِبْرَانِیَّۃِ مَاشَآءَ اللہُ اَنْ یَکْتُبَ.(بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدءالوحی الی رسول اللہ) یعنی ورقہ عبرانی زبان میں انجیل لکھاکرتے تھے.
Page 218
بعض روایات میں بجائے عبرانی کے عربی کالفظ بھی ہے.مگرہم اس روایت کو ترجیح دینے پر مجبور ہیں.کیونکہ اگر عربی میں تورات وانجیل ہوتی توبہت سے لوگ اس کے پڑھنے والے نکلتے.بلکہ میرے نزدیک تویہ بھی ممکن ہے کہ عبرانی بھی راوی کی غلطی سے لکھا گیاہو.کیونکہ اس وقت یونانی اناجیل ہی مروج تھیں اورعبرانی انجیل قریباً مفقود ہوچکی تھی.آنحضرت ؐکے صحابہ میں سے صرف عبداللہ بن سلام ہی عبرانی جانتے تھے (۳)تیسراثبوت اس امر کا کہ تورات کا ترجمہ عربی میں نہ ہواتھا یہ ہے کہ یہودی جن کے بعض قبائل مدینہ میں آکر بس گئے تھے.ان کے پاس بھی تورات کاعربی ترجمہ نہ تھا.چنانچہ اگر کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوکسی حوالہ کی ضرورت ہوتی توعبداللہ بن سلام سے آپ کومددلینی پڑتی تھی جوعبرانی جانتے تھے(مسلم کتاب الحدود باب رجم الیھود اھل الذمۃ والزنی).احادیث سے معلوم ہوتاہے کہ حضرت عمرؓ نے عبرانی پڑھنی شروع کی تھی تاکہ وہ تورات اور انجیل کو پڑھ سکیں (مشکٰوۃ المصابیح کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ) (۴)چوتھے ثبوت کے طور میں ایک مسیحی مضمون نویس کی شہاد ت پیش کرتاہوں.ڈاکٹر الگزنڈر سوٹر.ایم.اے.ایل.ایل.ڈی.اپنی کتاب دی ٹیکسٹ اینڈ کینن آ ف دی نیوٹسٹیمنٹ کے صفحہ ۷۴ پر لکھتے ہیں.۱؎ 'ARABIC VERSIONS: THESE COME PARTLY DIRECTLY FROM GREEK PARTLY THROUGH SYRIAC AND PARTLY THROUGH CAPTIC.MUHAMMAD HIMSELF KNEW THE GOSPEL STORY ONLY ORALLY.THE OLDEST MANUSCRIPT GOES NO FURTHER BACK THAN 8TH CENTURY ------------TWO VERSIONS OF THE ARABIC ARE REPORTED TO HAVE TAKEN PLACE AT ALAXANDRIA IN THE 13TH CENTURY.' THE TEXT & CANNON OF THE NEW TESTAMENT.'BY.DR.ALEXANDER SOUTER.M.A.L.L.D.PAGE 74 انجیل کے عربی تراجم کے عنوان کے نیچے لکھتے ہیں :.’’ان تراجم کے کچھ ٹکڑے توبراہ راست یونانی سے ہوئے کچھ ٹکڑے سریانی زبان سے ترجمہ ہو ئے اور کچھ قبطی زبان سے.محمد(صلعم)بھی اناجیل کے متعلق صرف زبانی معلومات رکھتے تھے.پرانے سے پرانا ترجمہ عربی
Page 219
کاآٹھو یںصدی سے اوپر نہیں جاتا.‘‘(رسول کریم صلعم چھٹی صدی میں پیداہوئے تھے ).پھر لکھتے ہیں کہ بیا ن کیا جاتا ہے کہ دو ترجمے عربی کے تیرہویں صدی میں اسکندر یہ کے مقام پرکئے گئے تھے.ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ انجیل کا عربی ترجمہ اس وقت تک نہ ہواتھا اورجن لوگو ںنے انجیل پڑھنی ہوتی تھی وہ عبرانی یایونانی میں پڑھا کرتے تھے.پس یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوسکتا کہ جبر عربی زبان میں تورا ت اور انجیل پڑھتا تھا اورآپ ا س سے سیکھ لیتے تھے.وہ عبرانی یونانی زبان کے الفاظ جو اس نے رٹے ہوئے ہوں گے پڑھاکرتا ہوگا.پس آپ زیادہ سے زیاد ہ یہ کرسکتے تھے کہ اس کے بولے ہوئے لفظوں کو یاد کرلیں.مگراس سے آپ کو کیافائدہ ہوسکتاتھا.آنحضرت ؐ پر کسی شخص سے سیکھنے کے اعتراض کےبعد ارتداد کا ذکر اور اس کی وجہ آخر میں ایک باریک اشارہ کوبھی واضح کردیناچاہتاہوں جس سے معلوم ہوتاہے کہ اس جگہ جس اعتراض کا ذکر کیاگیا ہے وہ جبر کے متعلق تھا.اوروہ اشار ہ یہ ہے کہ اس اعتراض کی تفصیلات کے بعد جو سب سے پہلی آیت ہے اس میں مرتدوں کا ذکرہے اورجبر کی زند گی کے ایک اہم واقعہ کا تعلق بھی ایک مرتد سے ہے.تفصیل اس کی یہ ہے کہ جبر د ل سے مسلمان ہوگئے تھے مگر ظاہر نہ کرتے تھے.رسول کریم صلعم جب مدینہ تشریف لے گئے تو ایک شخص کوکاتب وحی مقرر کیا جس کانام عبداللہ بن ابی سرح تھا.یہ وہاں قرآن کریم ہی کے متعلق ایک شبہ میں پڑ کر مرتد ہوگیا.اور جب مکہ میں آیا تولوگوں کو جبر کے مسلمان ہونے کی اطلاع دے دی.جس کی وجہ سے سالہا سال تک ان کو سخت تکالیف دی گئیں (العصابۃ ذکر جبر).پس اس اعتراض کے معاً بعد آیت ارتداد رکھ کر ایک باریک اشار ہ اس طرف کیا گیا ہے کہ اس متّہم غلام پر ایک زمانہ میں ایک مرتد کی طرف سے بھی ظلم ٹوٹنے والا ہے.آنحضرت ؐ پر کسی سے سیکھنے کے اعتراض کے جواب میں چار امور مذکورہ بالا اعتراضات کے بارہ میں بعض اور امور بھی بیان کردیتاہوں تاحسب ضرورت کام آئیں.(۱)قرآن کریم نے کسی ایک فرقہ کو نہیں لیا.بلکہ سب سے اختلاف کیا ہے وہ کس فرقہ کا آدمی تھا جواس کام میں آپ کی مدد کرتاتھا ؟ کیا وہ خود اپنے مذہب کے خلاف تعلیم بھی آ پ کوسکھاتا تھا ؟ (۲)قرآن کریم نے بائبل کے غلط واقعات کی اصلاح کی ہے.یہ اصلاح کس غلام کی مدد سے آپ کرسکتے تھے.جیسے مثلاً ہارونؑ کاشرک نہ کرنا اوردائود ؑ و سلیمان ؑ و نوح ؑ کی پاکیزگی ثابت کرنا یہ ایسے واقعات ہیں کہ آج تیرہ سوسال کے بعد یورپین مسیحی مصنف ان کے بارہ میں قرآن کریم کی تائید پر مجبور ہورہے ہیں.
Page 220
(۳)آپ نے بائبل کے واقعات کے متعلق بعض نئی باتیں بیان کی ہیں جن کااس وقت کسی یہودی اورعیسائی فرقہ کو بھی علم نہ تھا لیکن وہ آج سچی ثابت ہورہی ہیں.جیسے فرعون کی لاش کا محفوظ رہنا اورآخر مل جانا.(۴)روایات سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلعم چوتھے یا پانچویں سال بعد دعویٰ کے اس غلام کے پا س کھڑے ہواکرتے تھے کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جب آنحضرت صلعم کابائیکاٹ ہواہے اس وقت اس کے پاس کھڑے ہواکرتے تھے لیکن قرآن کریم کی بعض سورتیں اس واقعہ سے پہلے اتر چکی تھیں اوران میں عیسائیوں کا ذکر موجود تھا جیسے سورۃ طٰہٰ سورۃ فرقان.کہف.مریم وغیرہ.چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ جو بالکل ابتدائی زمانہ میں اسلام لانے والے ہیںفرماتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل.کہف.سورۃ طٰہٰ.سورۃ مریم.سورۃ انبیاء اِنَّ ھُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاَوَّلِ وَھُنَّ مِنْ تِلَادِیْ(بخاری کتاب التفسیر سورۃالانبیاء)یہ قرآن کریم کی ابتدائی سورتوں میں سے ہیں اور میرا پرانا مال ہیں یعنی میں نے ابتداءاسلام میں یہ سورتیں یاد کی تھیں.ان سورتوں میں کثرت سے یہودیوں اورعیسائیوں کے واقعا ت آتے ہیں.اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ١ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ جولوگ اللہ(تعالیٰ)کے نشانوں پر ایما ن نہیں لاتے انہیں اللہ (تعالیٰ)ہدایت نہیں دیتا اوران کے لئے دردناک وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۰۰۱۰۵ عذاب (مقدر)ہے.حلّ لُغَات.اَلْعَذَابُ اَلْعَذَابُکے معنوں کے لئے دیکھو حجر آیت نمبر ۵۱.اَلْعَذَابُ:کُلُّ مَاشَقَّ عَلَی الْاِنْسَانِ وَمَنَعَہٗ عَنْ مُرادِہِ.عذاب کے معنی ہیں جو انسان پر شاق گذرے اورحصول مراد سے اسے روک دے وَفِی الْکُلِّیَّاتِ کُلُّ عَذَابٍ فِی الْقُرْآنِ فَھُوَ التَّعْذِیْبُ اِلَّا وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَۃٌ فَاِنَّ الْمُرَادَ الضَّرْبُ.اورکلیات میں لکھا ہے کہ عذاب سے مراد قرآن مجید میں عذاب دیناہوتاہے سوائے آیت وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا کے.وہاں سزامراد ہے.(اقرب) اَلْاَلِیْمُ اَلْاَلِیْمُ اَلمُوْجِعُ دکھ دینے والا.(اقرب)
Page 221
تفسیر.یعنی چونکہ یہ لوگ ایسی زبردست آیتوں اورنشانوں کے ہوتے ہوئے بھی ایسے بیہودہ اعتراض کرتے ہیں.اورایسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم پربجائے ایمان لانے کے اس پر ہنسی کرتے ہیں.اس لئے یہ لوگ ضرورسزاپائیں گے.اِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ جھوٹ وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو اللہ(تعالیٰ)کےنشانوں پرایمان نہیں رکھتے اوریہی لوگ جھوٹ بولنے میں اللّٰهِ١ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ۰۰۱۰۶ کامل ہوتے ہیں.تفسیر.محمد رسول اللہ کی مسلمہ سچائی اس امر کا ثبوت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر افتراء نہیں کیا اس جگہ رسول کریم صلعم کی زندگی کوبطور نمونہ کے پیش کیاہے.اورکہا ہے کہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ تو وہی شخص بناسکتاہے جسے اللہ تعالیٰ کی طاقت پرایمان نہ ہو.مگر محمد رسول اللہ کو دیکھو کہ یہ تواللہ تعالیٰ کی عظمت دنیا میں قائم کررہے ہیں اورنہ صرف خود بلکہ لوگوں کوبھی یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کی تعظیم کرو.اس لئے ایسے شخص پراعتراض کرنا کسی سیاہ دل کاہی کام ہے.دوسرے یہ کام ایک عادی جھوٹے شخص کے سوادوسراشخص نہیں کرسکتا اورمحمد رسول اللہ کی سچائی کے گواہ توتم بھی ہو.مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ جولوگ (بھی)اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ(تعالیٰ)کاانکار کریں مگر وہ نہیں جنہیں (کفر پر)مجبورکیاگیا ہو اوران مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَ لٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا کا دل ایمان پر مطمئن ہو بلکہ وہ جنہوں نے (اپنا )سینہ کفر کے لئے کھول دیاہوان پر اللہ (تعالیٰ )
Page 222
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ١ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۰۰۱۰۷ کا(بہت)بڑاغضب (نازل)ہوگا اور ان کے لئے بڑا(بھاری)عذاب (مقدر)ہے.حلّ لُغَات.اُ کْرِہَ اُکْرِہَ اَکْرَہَ سے مجہول کاصیغہ ہے.اوراَکْرَھَہُ عَلَی الْاَمْرِ کے معنے ہیں.حَمَلَہٗ عَلَیْہِ قَھْرًا.کسی کو کسی کام پر زبردستی آمادہ کیا.اَکْرَ ہَ فُلَانًا :حَمَلَہٗ عَلیٰ اَمْرٍ یَکْرَھُہٗ.اس کوکسی ایسے کام پر آمادہ کیا جس کو وہ ناپسند کرتاتھا.وَقِیْلَ عَلَی أَمْرٍ لَا یُرِیْدُہٗ طَبْعًااَوْ شَرْعًا.اوربعض کہتے ہیں.اَکْرَہَ فُلَانًاکے معنے ہیں کہ اس نے اسے ایسے کام پر آمادہ کیا جس کو وہ طبعاً یامذہباً ناپسند کرتاتھا.ا س سے اسم فاعل مُکْرِہٌ اوراسم مفعول مُکْرَہٌ آتاہے.(اقرب) پہلے حصہ میں واحد کے صیغے استعمال ہوئے ہیں.لیکن ان پراللہ کاعذاب نازل ہوگا سے جمع کے.اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں مَنْ جمع کے لئے بھی آتا ہے اورمفرد کے لئے بھی.اور چونکہ یہ لفظ مفرد ہے.بعض دفعہ ا س کے بعد مفرد کے صیغے استعمال ہوتے ہیں مگر مراد جمع ہوتی ہے.ایسا ہی یہاں ہواہے.اس لئے معنوں کے مطابق اردو میں مفرد کی جگہ جمع کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں.ورنہ ترجمہ غلط ہوجاتا.(مفردات) قَلْبٌ.قَلْبٌ اَلْفُؤَادُ.دل.وقَدْیُطْلَقُ عَلَی الْعَقْلِ.اور کبھی قلب کالفظ عقل کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی جمع قُلُوْبٌ آتی ہے.(اقرب) مُطْمَئِنٌّ.مُطْـمَئِنُّ اِطْـمَأَنَّ سے اسم فاعل کاصیغہ ہے.اوراِطْـمَئَنَّ کے معنوںکے لئے دیکھو رعدآیت نمبر ۲۹.تَطْمَئِنَّ اِطْمَأَنَّ سے مضارع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اِطْمَئَنَّ اِلٰی کَذَا کے معنے ہیں سَکَنَ وَآ مَنَ لَہ.سکون پکڑا اور تسلی پائی.(اقرب) اَلْغَضَبُ.اَلْغَضَبُ ثَورَانُ دَمِ الْقَلْبِ اِرَادَۃَ الْاِنْتِقَامِ.سزادینے کے غرض سے دل کے خو ن کے جوش مارنے کا نام غضب ہے.وَاِذَا وُصِفَ اللہُ تَعَالیٰ بِہٖ فَالْمُرَادُ بِہِ الْاِنْتِقَامُ دُوْنَ غَیْرِہٖ.اورجب غضب کالفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوتاہے تواس کے معنے صرف سزادینے کے ہوتے ہیں.جوش وغیرہ کے معنے اس میں نہیں پائے جاتے.(مفردات) تفسیر.اس ضمنی اعتراض کا جواب دے کر کہ جب انہیں آئندہ زمانہ کی ترقیات کی پیشگوئیوں کی طرف
Page 223
توجہ دلائی جاتی ہے اوردلائل سے بتایاجاتا ہے کہ اس قسم کے روحانی حشر ہمیشہ دنیا میں ہوتے آئے ہیں توکفار اس بات سے فائدہ اٹھا کر کہ آئندہ کی پیشگوئیاںگذشتہ انبیاء کے واقعات کے پردہ میں بیان کی گئی ہیں جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ ہم توپہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ قرآن کسی دوسرے شخص کاسکھایاہواہے.وہ دوسری کتب کی باتیں ان کو سکھادیتا ہے.اب پھر ترقیا ت کے ذکر کی طر ف بات کو پھرایاگیا ہے اورادھر توجہ دلائی ہے کہ ترقیات کے ساتھ امن ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ بعض قسم کے فتنے بھی پیداہوجاتے ہیں.مخالفوں میں بھی مخالفت کازیادہ جوش پیدا ہوجاتا ہے.اس لئے اس زمانہ میں اپنے ایمانوں کا خاص طور پر خیال رکھنا.اوربتایا ہے کہ جو شخص کسی دنیوی غرض کی وجہ سے مرتد ہوگاوہ بڑے عذاب میں مبتلاکیاجائے گا.آیتمَنْ شَرَحَمیں عبد اللہ بن ابی سرح کے ارتداد کی پیشگوئی میرے نزدیک اس آیت میں عبد اللہ بن ابی سرح کے ارتداد کی پیشگوئی ہے.اورپہلی آیات سے اس آیت کا جو ربط میں پہلے بیان کرچکاہوں.اس کے علاوہ اسے یہ بھی ربط حاصل ہے کہ جبر کی وجہ سے جواعتراض ہواتھا اس میں بھی قرآن کریم کے انسانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کا ذکر تھا.اوریہ مرتد جس کایہاں ذکر ہے اس نے بھی ارتدا د اسی دلیل پر کیاتھا کہ قرآن خدائی کلام نہیں.انسانوں کابنایا ہواکلا م ہے.یہ پیشگوئی ایک زبردست پیشگوئی ہے.اور چونکہ مکہ میں کی گئی اوران حالات میں کی گئی کہ عبداللہ کوابھی کاتب وحی مقررنہ کیاگیاتھا.پھر اس میں اشارۃً وجہ ارتداد بھی بتائی گئی کہ اسے قرآن کریم کے الہامی ہونے کے بارہ میں شبہ ہوگا.اس لئے اس کی عظمت اوربھی بڑھ جاتی ہے.یہ جو آگے فرمایا ہے کہ جو مجبوراً ارتداد کرے اس پر اتنا عذاب نہیں.شاید یہ اشارہ جبر ہی کی طرف ہو.اورممکن ہے کہ ظلم کی وجہ سے وہ دلیر ی سے اسلام کااظہار نہ کرسکے ہوں.گوبعض روایات میں عمار کے متعلق اس کو چسپاں کیا جاتا ہے مگر مضمون کی ترتیب کودیکھتے ہوئے جبر پر یہ واقعہ زیادہ چسپاں ہوتاہے (تفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت ھذا).مسیحیوں نے اس آیت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ا س سے معلوم ہوتاہے کہ اسلام بزدلی کی تعلیم دیتاہے اورظلم کے موقعہ پر ارتداد کی اجازت دیتا ہے (تفسیر القرآن از پادری ویری ).لیکن یہ اعتراض بھی ان کے دوسرے اعتراضوں کی طرح غلط ہے.کیونکہ اس جگہ سے یہ ہرگز نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ اس فعل کو معا ف کردے گا.اس جگہ تو صرف یہ کہا ہے کہ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّ والے کے متعلق اس آیت میں حکم نہیں بیان کیا گیا.اورسزا سے مستثنیٰ نہیں بتایاگیا.بلکہ اس گروہ کو علیحدہ قراردے کر یہ کہا ہے کہ ا س کا ذکر بعد میں کیاجائے گا.
Page 224
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ١ۙ وَ اَنَّ (اور)ایسا اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے اس ورلی زندگی سے محبت کرکےا سے آخرت پر مقدم کرلیا اور(نیز اس اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ۰۰۱۰۸ وجہ سے )کہ اللہ (تعالیٰ) کفر اختیار کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.حلّ لُغَات.اِستَحَبُّوْا.اِسْتَحَبُّوْا اِسْتَحَبَّ سے جمع کاصیغہ ہے اوراِسْتَحَبَّہٗ کے معنے اَحَبَّہٗ اس سے محبت کی.اِسْتَحْسَنَہٗ اس کو پسند کیا.اِسْتَحَبَّ الْکُفْرَ عَلَی الْاِیْمَانِ کفرکو ایمان پر ترجیح دی (اقرب)پس اِسْتَحَبُّوا الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا عَلَی الْاٰخِرَۃِ کے معنے ہوں گے کہ انہوں نے اس ورلی زندگی سے محبت کرکے اسے آخرت پر ترجیح دی.تفسیر.اسلام سے بے زاری کسی دنیوی فائدہ کے لئے ہی ہو سکتی ہے اس آیت میں یہ بتایاہے کہ اسلام چونکہ اللہ تعالیٰ کی طر ف سے نازل شدہ ایک صداقت ہے.اس سے بیزارہوکر کوئی مرتد نہیں ہوسکتا.جوہوگادنیوی اغراض سے ہوگا.اورایساآدمی خدا تعالیٰ سے کسی نیک سلوک کاکب امیدوار ہو سکتا ہے.اس آیت سے عبداللہ کے اس دعویٰ کورد کیا ہے کہ میں یہ دیکھ کر کہ قرآن انسانی کلام ہے مرتد ہوا ہوں.اور بتایا ہے کہ یہ شخص ظاہر کچھ اَورکرے گامگراصل وجہ دنیاوی لالچ ہوگی.اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ یہ وہ لوگ ہیں جن (کے کفر کی وجہ سے ان)کے دلوںاوران کے کانوں اوران کی آنکھو ں پر اللہ(تعالیٰ) نے مہر اَبْصَارِهِمْ١ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ۰۰۱۰۹لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ لگادی ہے اوریہ لو گ ہی ہیں جو پکے غافل ہیں.(اور)اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی
Page 225
فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۰۰۱۱۰ آخر ت میں (سب سے)زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے.حلّ لُغَات.طَبَعَ عَلَیْہِ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۷۵.طَبَعَ الشَّیْءَ :صَوَّرَہُ بِصُوْرَۃٍ مَّا اس کی کوئی صورت یا شکل بنائی.عَلَیْہِ: خَتَمَ مہر لگائی.اللہُ الخَلْقَ خَلَقَہُمْ پیدا کیا.السَّیْفَ عَمِلَہُ وَصَاغَہُ بنایا.اَلدِّرْھَمَ نَقَشَہُ وَسَکَّہُ مضروب کیا.(اقرب) تفسیر.یعنی جولوگ غلط فہمی میں مبتلاہوکر دین حق کو نہیں چھوڑتے بلکہ دوسری اغراض کے ماتحت ایسا کرتے ہیں.ان کی آنکھوں ،کانوںاوردلوں پر مہر لگ جاتی ہے کیونکہ وہ بدترین نمونہ اخلاق کاپیش کرتے ہیں.اورایک بڑی نعمت کو محض چھوٹے سے فائدے کے لئے قربان کردیتے ہیں.لَاجَرَمَ اَنَّہُمْ الخ.یعنی جب ایسے شخصوںکو ہم اس دنیا میں ذلیل کریں گے تواس میں تو کوئی شبہ رہتا ہی نہیں کہ وہ آخرت میں بھی عذاب پائیں گے کیونکہ ایسے گناہوں کی سزاکا اصل مقام وہی ہے.ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ اورتیرارب یقیناً ان لوگوں کے لئے جو دکھ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کرگئے پھر انہوں نے جہاد کیا اور(اپنے جٰهَدُوْا وَ صَبَرُوْۤا١ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ عہد پر)ثابت قدم رہے (ہاں )تیرارب یقیناً اس (شرط کوپوراکرنے)کے بعد(ان کے لئے )بہت بخشنے والا رَّحِيْمٌؒ۰۰۱۱۱ (اور)باربار رحم کرنے والا(ثابت)ہوگا.حلّ لُغَات.فُتِنُوْا.فُتِنُوْا فَتَنَہٗ سے مجہول کاصیغہ ہے.اورفَتَنَ (فَتْنًاوفُتُوْنًا)زَیْدٌ عَمْرًا کے معنے ہیں اَوْقَعَہٗ فِی الْفِتْنَۃِ فَفَتَنَ ھُوَ اَیْ وَقَعَ فِیْہَا اس کو فتنہ میں ڈالا اوروہ فتنہ میں پڑگیا.(لازم اورمتعدی دونوں طرح استعمال ہوتاہے )
Page 226
فَتَنَہٗ کے معنے ہیں اَعْـجَبَہٗ.وہ اس کو پسند آیا.اَلْمَالُ النَّاسَ: اِسْتَمَا لَھُمْ.مال نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرلیا.فَتَنَہٗ فِتْنَۃً:خَبَرَہٗ اس کو آزمایا.فُلانًا: اَضَلَّہٗ اس کو گمراہ کیا.فَتَنَ فُلَانًا عَنْ رَأْیِہٖ صَدَّہٗ.اس کو اس کی رائے سے روکا.فَتَنَ الصَّائِغُ الذَّھَبَ وَالْفِضَّۃَ:اَذَابَہُ وَاَحْرَقَہ بِالنَّارِ لِیُبَیِّنَ الْجَیِّدَ مِنَ الرَّدِیْءِ وَیُعْلَمَ اَنَّہٗ خَالِصٌ اَوْ مَشُوْبٌ.سنار نے سونے کو آگ میں ڈال کر پگھلایا تاکہ اس کے کھرے اورکھوٹے کو معلوم کرے.اورفُتِنَ الرَّجُلُ فِی دِیْنِہٖ کے معنے ہیں مَالَ عَنْہُ اپنے دین سے علیحدہ ہوگیا.فُتِنَ فُلَانٌ اَصَابَتْہُ فِتْنَۃٌ فذَھَبَ مَالُہٗ اَوْ عَقْلُہٗ اس پر مصیبت نازل ہوئی اوراس کی وجہ سے اس کامال یا عقل جاتی رہی.وَکَذَالِکَ اِذَااخْتُبِرَ اورجب کسی کاامتحان لیا جائے تو فُتِنَ صیغہ مجہول اس کے لئے استعمال ہوتاہے (اقرب) پس فُتِنُوْاکے ایک معنے یہ ہوں گے کہ انہیں دکھ میں ڈالاگیا.جَاھَدُوْا.جَاھَدُ وْاجَاھَدَ سے جمع کا صیغہ ہے.اورجَاھَدَفِی سَبِیْلِ اللہ ِ (مُجَاھَدَۃً وَجِھَادًا)کے معنے ہیں.بَذَلَ وُسْعَہٗ اللہ کے دین کے لئے انتہائی کوشش کی.جَاھَدَ الْعَدُوَّ.قَاتَلَہٗ دشمن سے لڑا (اقرب) پس جَاھَدُوْا کے معنے ہوں گے (۱)انہوں نے جہاد کیا (۲)انہوں نے اللہ کے دین کے لئے کوشش کی.تفسیر.اِلَّامَنْ اُکْرِہَ کے ماتحت توبہ قبول کئے جانے والوں کے لئے چار شرائط اس آیت میں ان لوگوں کاحکم بتایاگیا ہے جن کو پہلے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ کے الفاظ سے مستثنیٰ بتایا گیا تھا ان کاحکم یہ بتاتاہے کہ اگر کسی سے ایسی غلطی ہوجائے کہ وہ ظلم کی برداشت نہ کرکے ظاہراً ارتداد کرلے گو دل میں مطمئن ہو تواس کے لئے یہ حکم ہے کہ اول وہ اس مقام کوچھوڑ دے جہاں اُسے لوگوں سے دب کر ارتداد کرنا پڑا.(۲)دوسرے وہ دین کی اشاعت میں لگ جائے اوراپنے آپ کو دین کے لئے گویا وقف کردے.(۳)تیسرے یہ مجاہدہ بند نہ کرے بلکہ استقلال سے اس پر قائم رہے.اوراپنے ظاہری ارتداد کے بدلہ میں دوسرے لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرے.(۴)آئندہ اس سے پھر ایسی خطاظاہر نہ ہو.اگر وہ ان باتوں پرعمل کرے توفرماتا ہے کہ ان سب کاموں کے کرلینے کے بعد تیرارب اس شخص کو معاف فرمادے گا.ان قربانیوںکے بعد توبہ قبول کرنے کاحکم ہوتے ہوئے مسیحی مصنفوں کا یہ لکھنا کہ اسلام نے ظلم کے وقت ظاہری انکار کی اجازت دی ہے ان مظالم میں سے ایک ظلم ہے جومسیحی پادری اسلام پرکرتے چلے آتے ہیں.(تفسیر القرآن از ویری جلد ۳ صفحہ ۴۷).
Page 227
يَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَ تُوَفّٰى كُلُّ (اس جزاکاظہورخصوصیت سے اس دن ہوگا )جس دن ہرشخص اپنی جان کے متعلق جھگڑتاہواآئے گااورہرشخص نے نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۰۰۱۱۲ جوکچھ کیا ہوگا(ا س کااجر )اسے پوراپورادیا جائے گااوران پر (کسی رنگ میں بھی )ظلم نہ کیاجائے گا.حلّ لُغَات.تُجَادِلُ.تُجَادِلُ جَادَلَ سے واحد مؤنث غائب کاصیغہ ہے.اورجَادَلَہٗ (مُجَادَلَۃً وَ جِدَالًا) کے معنے ہیں خَاصَمَہٗ شَدِیْدًااس نے اس سے سخت جھگڑاکیا.(اقرب) پسيَوْمَ تَاْتِيْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا کے معنے ہوں گے جس دن ہرشخص اپنی جان کے متعلق جھگڑتا ہواآئے گا.تُوَفّٰی.تُوَفّٰی وَفّٰی(باب تفعیل)سے مضارع واحد مؤنث غائب کاصیغہ ہے.اوروَفّٰی کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۱۰۵.یَتَوَفّٰی کا مادہ وَفٰی اور ماخذ وَفَاۃٌ ہے اور یہ باب تفعّل سے فعل مضارع ہے.وفات کے معنی موت کے ہیں اور تَوَفَّی کے معنی موت وارد کرنے اور جان نکال لینے کے ہیں.اقرب الموارد میں ہے تَوَفّی اللہُ زَیْدً ا:قَبَضَ رُوْحَہٗ اللہ تعالیٰ نے زید کی روح قبض کرلی یا جان نکال لی.تُوُفِّیَ فُلَانٌ مَجْہُوْلًا قُبِضَتْ رُوْحُہٗ وَمَاتَ.تُوَفِّیَ بصیغہ مجہول کے معنی ہیں اس کی جان نکال لی گئی اور وہ مر گیا.فَاللہُ الْمُتَوَفِّیْ وَالْعَبْدُ الْمُتَوَفّٰی.غرض اللہ تعالیٰ مُتَوَفِّی یعنی وفات دینے والا ہوتا ہے اور انسان مُتَوَفّٰی یعنی وفات پانے والا.اور قاموس میں ہے اَوْفٰی فُلَانًا حَقَّہٗ وَوَفَّاہُ وَوَافَاہُ فَاسْتَوْفَاہُ وَتَوَفَّاہُ وَالْوَفَاۃُ الْمَوْتُ وَتَوَفَّاہُ اللہُ قَبَضَ رُوْحَہٗ کہ جو لفظ تَوَفّی اِسْتِیْفَاء یعنی پورا پورا لینے کے معنی دیتا ہے وہ اِیْفَاءٌ تَوْفِیَۃٌ اور مُوَافَاۃٌ کا مطاوع اور لفظ وَفَی سے ماخوذ ہوتا ہے.اور اس کا مفعول کوئی حق یا کوئی مالیت ہوتی ہے.اور جس لفظ تَوَفّی کے معنی قبض روح کے ہوتے ہیں وہ لفظ وَفَاۃٌ سے ماخوذ ہوتا ہے.جس کے معنی موت کے ہیں اور تَوَفَّاہُ اللہُ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرلی.یعنی جان نکال لی.اور کلّیات ابوالبقاء میں ہے وَالْفِعْلُ مِنَ الْوَفَاۃِ یعنی یہ فعل لفظ وَفَاۃٌ سے ماخوذ ہے.جس کے معنی موت کے ہیں.
Page 228
تفسیر.یَوْمَغَفُوْرٌرَّحِیْمٌ کاظر ف ہے.مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہرشخص اپنے انجام کی اہمیت سمجھ کر پورازورلگائے گاکہ کسی طرح میں گرفتاری سے بچ جائوں اس وقت اللہ تعالیٰ ان لو گوں سے جو کمزوری دکھا کربعد میں ساری عمر اصلاح اورقربانی وغیرہ میں لگے رہیں گے غفورورحیم کاسلوک کرے گا.آیت ارتداد سے بزدلی سیکھانے کا اعتراض کرنے والوں کو جواب جولوگ آیت ارتدادسے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس میں بزدلی کی تعلیم دی گئی ہے.ان آیات پر غور کریں کہ کتنی بڑی قربانی ایسے لوگوں سے چاہی گئی ہے.جوشخص اس قربانی کی اہمیت کوسمجھے گا وہ امتحان کے موقعہ پر بزدلی دکھا ئے گاہی کیوں.کیونکہ بزدل آدمی اس قدرقربانی کرنے کی طاقت کہاں رکھتا ہے کہ ترک وطن کرے.جہا د فی سبیل اللہ کرے اوراپنے نفس کوساری عمر اس کا م میں لگائے رکھے.ان کاموں کی توفیق تووہی پائے گاجن سے کسی عارضی غفلت کی وجہ سے غلطی ہوگئی ہو یا جوبعد میں سچی توبہ کرچکا ہو.حضرت عمر ؐ کے زمانہ میں مرتد کا دوبارہ مسلمان ہونا حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک مرتد مدعی نبوت دوبارہ مسلمان ہوا.اس سے جو آپ نے سلوک کیا وہ گویا اس آیت کی تفسیر ہے.اس شخص کانام طلیحہ ابن خویلداسدی تھا.یہ مسلمانوں کے خلاف بعض جنگوں میں شامل ہواتھا.کچھ عرصہ کے بعدا س نے اسلام میں داخل ہوناچاہا.مگر حضرت عمرؓ نے اس کو معاف نہ کیا.ایک دفعہ ایسااتفاق ہو اکہ ایک صحابی شرحبیل بن حسنہؓ(جوبظاہر بہت د بلے پتلے اورکمزور تھے مگر فنِ جنگ کے بڑے ماہر تھے )ایک لڑائی میں ایک کافر سردار کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اس سردار نے یہ دیکھ کرکہ تلوار کی جنگ میں مَیںان کا مقابلہ نہیں کرسکتا جلدی سے آگے بڑھ کر ان کو کمرسے پکڑ لیا اورنیچے گراکر چھاتی پر چڑھ گیا.قریب تھا کہ وہ آپ کو قتل کردیتاکہ طلیحہ بن خویلد جو دل سے مسلمان ہوچکا تھا لیکن بوجہ حضرت عمرؓ کے توبہ قبول نہ کرنے کے اب تک کفار ہی میںشامل تھا.اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے ایمان کو چھپا نہ سکا اورآگے بڑھ کر اس کافر سردار پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کاسرتن سے جداہوگیا اور حضرت شرحبیلؓ کی جان بچ گئی.اس واقعہ سے باقی مسلمان بہت متاثر ہوئے.اورانہوں نے حضرت عمرؓ کے پاس سفارش کی کہ اسے معاف کردیاجائے.اس پرحضرت عمرؓ نے فرمایاکہ میں اس شرط پر معاف کرتا ہوں کہ یہ شخص اپنی ساری بقیہ زندگی جہاد میں گزارے اوراسلامی مملکت کی سرحدوںپرزندگی بسر کرے.چنانچہ وہ ہمیشہ سرحد پر ہی رہتے تھے اورکفار سے لڑائی کرتے رہتے تھے آخراسی حالت میں وفات پاگئے گواس شخص نے جان بوجھ کر ارتداد کیاتھا مگر معلوم ہوتاہے حضرت عمرؓ نے اسی آیت سے استدلال کرکے اس کے مشابہ حکم اس کو دےدیا.
Page 229
وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕنَّةً اوراللہ(تعالیٰ)نے (تمہیں سمجھا نے کے لئے )ایک بستی کا حال بیان کیا ہے جسے (ہرطرح سے )امن حاصل يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ ہے(اور)اطمینان نصیب ہے ہرطرف سے اس کارزق اسے بافراغت پہنچ رہا ہے.پھر(بھی )اس نے اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا اللہ(تعالیٰ) کی نعمتوں کی ناشکری کی ہےاس(کی اس ناشکری) پر اللہ (تعالیٰ)نے اس(کے باشندوں)پران يَصْنَعُوْنَ۰۰۱۱۳ کے اپنے (گھنونے)عمل کی وجہ سے بھوک اورخوف کالباس نازل کیااوراس کامزہ چکھایا.حلّ لُغَات.ضَرَبَ اللّٰہُ مَثَلًا ضَرَبَ اللّٰہُ مَثَلًاکے معنوںکے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر ۲۵.ضَرَبَ لَہٗ مَثَلًا کے معنے ہیں وَصَفَہٗ وَقَالَہٗ وَبَیَّنَہٗ مثل کو بیان کیا.ا ور اچھی طرح سے واضح کیا.رَغَدًا رَغَدَ عَیْشُہٗ رَغَدًا کے معنے ہیں طَابَ وَاتَّسَعَ اس کی زندگی خوشگوار اورکشادہ ہوگئی وَعَیْشَۃٌ رَغدٌ کے معنی ہیں واسعَۃٌ طَیِّبَۃٌ آسودہ زندگی.(اقرب) اَذَاقَ اَذَاقَھَااللّٰہُ لِبَاسَ الْجُوْعِ.اَذَاقَ ذَاقَ سے بناہے.ذَاقَ الْعَذَابَ وَالْمَکْرُوْہَ کے معنے ہیں نَـزَلَ بِہٖ فَقَاسَاہُ اس پر مصیبت نازل ہوئی اوراس نے سہی.اَذَاقَہٗ:صَیَّرَہُ یَذُوْقُ اسے چکھایا.(اقرب) پس اَذَاقَھَاللّٰہُ لِبَاسَ الْجُوْعِ کے معنے ہوں گے اللہ نے اس پر بھوک کاعذاب نازل کیا اوراس کو اس کا مزہ چکھایا.تفسیر.اس آیت میں مکہ کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہے.اس سے پہلے کفراوراسلام کا مقابلہ کیاگیا تھا.مگرکفار کے دل میں یہ خیال ہوسکتاتھا کہ شاید مکہ بوجہ اس تقدس کے جو اسے حاصل ہے مغلوب ہونے سے محفوظ رہے کیونکہ قریب زمانہ میں ابرہہ کے لشکرکی شکست کے ذریعہ وہ مکہ کی حفاظت کا نظارہ دیکھ چکے تھے ان کے اس جھوٹے اطمینا ن کو بھی اس آیت میں رد کر دیاگیاہے فرماتا ہے کہ مکہ بھی ایسے مجرموں کو نہیں بچاسکتا.مکہ کاامن بھی
Page 230
خوف اورقحط سے جاتارہے گا.کیونکہ ساکنین مکہ کے اعمال انہیں فضل الٰہی سے محروم کررہے ہیں.یہ دونوں عذاب ہجرت کے بعد مکہ والوں پر آئے.خوف توجنگوں کالازمی نتیجہ ہے.بھوک کاعذاب بھی آیا جبکہ ان کے کئی قافلے مسلمانوں کے ہاتھ پڑے اوران کی ضرورتوں کے سامان جنگوں میں ان کے ہاتھو ںسے چھین لئے گئے.عذاب کے ساتھ لباس کا ذکر لانے کی وجہ لباس کالفظ اس امر کے بتانے کے لئے استعمال فرمایا ہے کہ دونو عذاب سخت ہوںگے اور ان کے بدن پر ان کے آثار ظاہرہونے لگیں گے.دبلے ہوجائیں گے زرد پڑ جائیں گے.گویابھوک اورخوف کے اثرات ان کے جسم کو اس طرح ڈھانپ لیں گے جس طرح لباس جسم کو ڈھانک لیتا ہے.وَ لَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ اوریقیناًان کے پاس انہی میں سے (ہمارا)ایک رسول آچکا ہے مگرانہوں نے اسے جھٹلایاجس پر اس حالت میں کہ الْعَذَابُ وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ۰۰۱۱۴ وہ ظلم کررہے تھے (ہمارے )عذاب نے انہیں آپکڑا.تفسیر.اس آیت میں اوروضاحت کردی ہے کہ یہاں سے مکہ والے ہی مراد ہیں.فرمایا اس بستی والوں پر حجت پوری ہوگئی انہیں سمجھا نے کے لئے رسول آیا پھر وہ رسول بھی ان میں سے تھا باہر سے نہ تھا کہ کہہ دیتے ہم اس کے حالات سے واقف نہیں اس کے سچ اورجھو ٹ کااندازہ نہیں لگاسکتے.مگرباوجود اس کی خیر خواہی کے اوراس کے اخلاق حمیدہ کے معلو م ہونے کے انہوں نے اس کی تکذیب کی جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کافیصلہ کردیا.یہاں دوالزام ان پر لگائے ہیں.ایک تویہ کہ خدا کے رسولؐ کا انکار کیا.دوسرے اپنے مشاہدہ کاانکار کیا کہ باوجود رسول کریم صلعم کی صداقت سے واقف ہونے کے آپ کے دعوے کے منکر ہو گئے.وَ هُمْ ظٰلِمُوْنَ میں بتایا کہ عذاب ان کے ظلم ہی کی حالت میں ان کو پکڑ لے گا.یعنی یوں نہ ہوگا کہ ان کے اعمال کے بدلے ان کی اولاد وں سے لئے جائیں بلکہ ان کے اعمال کی سزا یہ ظالم خود ہی بھگتیں گے.
Page 231
فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا١۪ وَّ اشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ پس جو حلال (اور)طیب (مال)اللہ(تعالیٰ)نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے کھائو اوراللہ (تعالیٰ)کی نعمت کا اگر تم اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۰۰۱۱۵ اسی کی عبادت کرتے ہو شکر کرو.تفسیر.پہلی آیت میں کفارکے لئے بھوک اورخوف کے عذاب کی خبر دی تھی.اب اس آیت میں مومنوں کے لئے فراخیِ رزق اورفراغتِ بال کی خبر دی.اورفرمایاکفار کا رزق چھینا جائے گا.مسلمانوں کابڑھایا جائے گا.مگرایک فرق بھی ہوگاکہ کفار توجائز ناجائز سب ذرائع سے مال کما تے تھے.مسلمانوں کو حلال رزق ملے گا جو طیب بھی ہو گا.یعنی صحتوں کو اچھاکرنے والا ہوگا.اس میں خوف کی بھی نفی کی.کیونکہ کھانا جسم کوتبھی فائدہ پہنچاتاہے جب غم اورخوف نہ ہو.پس طیب رزق یعنی جسم اوردماغ اوردل کو تقویت اورصحت بخشنے والے کھانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے دلوں کو غم اورخوف سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا.چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کاشکر کروکے الفاظ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ تم کو بافراغت کھانا اورمطمئن دل عطافرمائے ہیں.پس اس ظاہری باطنی نعمت کے بدلہ میں اللہ تعالی کا شکراداکرو.خدا تعالیٰ کے لئےشکر ادا کرنے پر ایک اعتراض اور اس کا جواب بعض لوگ شکر پر اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو کسی کے شکر کی کیا احتیاج ہے ؟ اول تویہ اعتراض فضول ہے کیونکہ شکر ایک طبعی اظہار ہے جو ہراحسان کے بعد شریف آدمی کادل اپنی ممنونیت بتانے کے لئے کرتاہے.اس کے پیدا ہونے میں ضرورت یاعدم ضرورت کا کوئی سوال ہی نہیں.دوسرے جیساکہ اس آیت میں بتایا گیاہے شکرسے توحید کاعقیدہ مضبوط ہوتا ہے.جس طرح ظاہر جسم کوایک ہی قسم کاکام کرنے سے عادت پڑ جاتی ہے اسی طرح قلب اوردماغ کو بھی متواترہونے والے سے اعمال کی عادت پڑ جاتی ہے.پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجالاتے رہتے ہیں ان کے دماغ پراوردل پر ایک مستقل اثر باقی رہ جاتا ہے.اورہر نعمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے وہ عادی ہوجاتے یں.اورمشرکانہ خیال سے محفوظ ہوجاتے ہیں.
Page 232
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ اس نے تم پر صرف مردار کو خون کو اورسؤر کے گوشت کو اور(ہر)اس چیز کو حرام کیا ہے جس پر اللہ (تعالیٰ) کے سواکسی مَاۤ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ١ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ اورکانام لیا گیاہو اورجوشخص(ان میں سے کسی چیز کے کھانے پر )مجبورکیاجائے بحالیکہ وہ نہ باغی ہو اورنہ حد سے فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰۰۱۱۶ بڑھنے والاہو تو(یاد رہے کہ )اللہ(تعالیٰ)یقیناًبہت ہی بخشنے والا (اور)بارباررحم کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.اُھِلَّ.اُھِلَّ اَھَلَّسے مجہول کا صیغہ ہے اوراَھَلَّ الْقَوْمُ الْھِلَالَ کے معنے ہیں رفَعُوْا اَصْوَاتَھُمْ عِنْدَ رُؤْیَتِہٖ.لوگوں نے چاند کو دیکھ کر اپنی آوازوں کو بلند کیا.اَھَلَّ الصَّبِیُّ:رَفَعَ صَوْتَہُ بِالْبُکَاءِ.بچے نے روتے ہوئے آواز بلند کی.اَھَلَّ فُلَانٌ بِذِکرِاللہ : رَفَعَ صَوْتَہٗ بِہٖ عِنْدَ نِعْمَۃٍ اَوْ رُؤْ یَۃِ شَیْءٍ یُعْجِبُہٗ کسی نعمت کے ملنے پر یاکسی خوش کن چیز کے دیکھنے پر اللہ تعالیٰ کانام اونچی آواز سے لیا.اَھَلَّ بِالتَّسْمِیَّۃِ عَلَی الذَّبِیْحَۃِ اَیْ قَالَ بِسْمِ اللہِ.جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کانام لیا.مَآ اُھِلَّ بِہٖ لِغَیْرِاللہِ اَیْ نُوْدِیَ عَلَیْہِ بِغَیْرِ اسْمِ اللہِ عِنْدَ ذَبْحِہٖ.جانورکو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سواکسی اورکا نام لیا.(اقرب) فَمَن اضْطُرَّ.یہ اِضْطَرَّ سے مجہول کا صیغہ ہے اِضْطَرَّہٗ اِلَیْہِ کے معنے ہیں اَحْوَجَہٗ وَاَلْجَاَہٗ فَاضْطُرَّ.اس کواس کا محتاج بنا کر اس کی طرف جانے کے لئے لاچار کیا اوروہ اس کی طرف لاچار اورمجبورہوکر گیا.(اقرب) تفسیر.پہلی آیت میں فرمایا تھاکہ اے مسلمانوںتم کو اللہ تعالیٰ رزق کی فراخی دینے لگاہے اس وقت کے آنے سے پہلے ہی یہ سبق سیکھ لو کہ حلال اشیاء کااستعمال جو طیب بھی ہوںتم کوجائز ہوگا.یاد رہے کہ مال کی حلت ذریعہ کسب کے صحیح ہونے پر مبنی ہوتی ہے.مگرخوردنی اشیاء کے لئے اس کے علاو ہ ایک اورشرط بھی ہے اوروہ یہ کہ وہ اس قسم میں شامل نہ ہوں جسے حرام کیاگیاہے.پس اس سوال کو کہ کونسی اشیاء حلال ہیں اورکونسی حرام اس آیت میں حل کیاگیا ہے.الفاظ قرآنیہ بتاتے ہیں کہ اشیاء کی حلّت و حرمت میں اصل حلت ہے اورحرمت ایک قید کے طورپر ہے.بعض
Page 233
لوگوںکو خیا ل ہے کہ ہرشے حرام ہے سوائے اس کے جسے خدا تعالیٰ نے جائز کردیاہو.کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اورمالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کااستعمال جائز نہیں ہوتا.لیکن یہ درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماچکا ہے کہ ہم نے ہرچیز انسان کے لئے پیداکی ہے اوراس کے لئے مسخر کردی ہے.پس اس عام حکم سے ہرچیز انسان کے لئے جائز ہوگئی سوائے اس کے جس سے نصّاً یا اشارۃً روک دیاگیاہو.لحم خنزیر میں چربی کے شامل ہونے کے متعلق فقہاء کا اختلاف اس آیت میں جو لَحْمُ الْخِنْزِیْرِ فرمایا اس کے متعلق فقہاء میں اختلاف ہے کہ لحم میں چربی بھی شامل ہے یانہیں (القرطبی زیر آیت ھذا).جہاں تک لغت کاسوال ہے شَحْمٌ یعنی چربی کو لَحْمٌ سے الگ قسم کا خیال کیا جاتا ہے.لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ لحم کے نام میں شحم بھی شامل ہے.گومفسرین کی دلیل ذوقی ہے اورلغت والوں کی بات اس مسئلہ میں زیادہ قابل اعتبار ہے.مگر اس کے باوجود میرے نزدیک سؤر کی شحم یعنی چربی جائز نہیں.اوراس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ نبی کریم صلعم نے فرمایا ہے کہ مردہ جانور کی چربی حرام ہے (بخاری کتاب البیوع باب بیع المیتة).اورسؤر کی حرمت اورمردہ کی حرمت ایک ہی آیت میں اورایک ہی الفاظ میں بیان کی گئی ہے.پس دونوں کاحکم ایک قسم کا سمجھاجائے گا.لیکن سؤر کی جلد کااستعمال جائز ہوگا کیونکہ وہ کھائی نہیں جاتی.احادیث میں ایک واقعہ بیان کیاگیا ہے کہ حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا کی ایک بکری مرگئی.چند آدمی اس کو اٹھا کر باہر لئے جارہے تھے.نبی کریم صلعم نے ان سے فرمایا کہ تم اس کا چمڑا کیوں نہیں اتار لیتے ؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ یہ تومیتہ ہے.آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے کھاناہے (مسند احمد بن حنبل ).پس معلوم ہواکہ جس کاگوشت حرام ہو اس کے چمڑے کے استعمال میں کو ئی حرج نہیں.ہاںسؤر کے بالوں کے بنے ہو ئے بُرشوں کومکروہ کہا جائے گا.کیونکہ ان کو منہ میں ڈالاجاتاہے جوکھانے کادروازہ ہے.کیا بیان شدہ صرف چار چیزیں ہی حرام ہیں اس آیت کے متعلق ایک بہت بڑاسوال یہ پیدا ہوتاہے کہ اس میں چار چیزوں کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے.کیایہی چا ر چیز یں حرام ہیں اوران کے سوااورکوئی چیز حرام نہیں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر جوحصر پایا جاتاہے یہ حصر اضافی ہے.یعنی کفار کے حرام کو مدنظر رکھ کر اضافی طور پر ان چیز وں کو حرام کیاگیا ہے (تفسیر مظہری زیر آیت ھذا).چونکہ وہ سائبہ وغیرہ کو حرام کہا کرتے تھے.خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام نہیں حرام تو یہ اشیا ء ہیں جو ہم گنوارہے ہیں.اس صورت بیان میں حصر تعداد کا نہیں ہواکرتا بلکہ اقسام کاہواکرتا ہے.پس آیت کا مفہو م یہ ہوگا کہ اس قسم کی چیزیں حرام نہیں جو تم کہتے ہو.بلکہ اس قسم کی چیزیں
Page 234
حرام ہیں جو ہم بتاتے ہیں.اورحرمت کی نفی بقیہ اشیاء کے متعلق نہیں سمجھی جائے گی بلکہ ان اشیاء کے متعلق سمجھی جائے گی جن کاحرام ہوناکفار بیان کرتے تھے.بعض نے کہا ہے کہ جب یہ آیت ناز ل ہوئی تھی اس وقت تک یہی چا رچیزیں حرام تھیں باقی بعد میں ہوئیں.یہ جواب واقعات کے لحاظ سے بھی غلط ہے اوراس لئے بھی کہ اس سے آیت کے لفظ اِنَّمَا کوآئندہ کے لئے منسوخ ماننا پڑتا ہے مگرقرآن کریم کاکوئی لفظ منسوخ نہیں.بعض نے مجبورہوکر کہہ دیا ہے کہ یہی چارچیزیں حرا م ہیں.ان کے سوااورکوئی شے حرام نہیں(تفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت ھذا).اس آیت میں حصر زمانی یا حصر اضافی میر ے نزدیک حصر اضافی بعض صورتوں میں جائز ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر حصر انہی چار چیزوں پرکیا گیا ہے.یہ ذکرچار سورتوں میں ہے.سورۃ نحل.بقرہ.انعام.مائدہ.سورۃ نحل اورانعام میں تواس سے پہلے یہ ذکر موجو دہے کہ کفار اپنی مرضی سے مختلف اشیاء کو حلال و حرام کرلیتے تھے.مگر سورۃ مائدہ اوربقرہ میں یہ ذکر بالکل نہیں.سورۃ بقرہ میں تواعمال خیر کے مسئلہ میں اس مسئلہ کو بیا ن کیا ہے اورسور ۃ مائدہ میں کفارکے حلال و حرام کرنے کا ذکر کئے بغیر حلال وحرام کی ایک مستقل بحث کی گئی ہے.اوراس جگہ حرام اشیاء کو بھی گنایاگیا ہے.پس چونکہ دواورسورتوں میں حصر توموجود ہے مگر ان میں کفار کے حلال و حرام کرنے کاکوئی ذکرنہیں.اس لئے اس حصر کو اضافی قرار دینا ٹھیک معلوم نہیں ہوتا.آیت میں حصر زمانی درست معلوم نہیں ہوتا جنہوں نے کہاہے کہ حصر زمانی لحاظ سے ہے ان کا قول بھی درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ مکہ کے زمانہ تک تویہ تشریح درست ہوسکتی تھی.مگر یہی آیات سورۃ بقرہ میں بھی نازل ہوئی ہیں.جس کا زمانہ ہجرت کے تیسرے سال تک پہنچتا ہے.اورمائدہ میں بھی نازل ہوئی ہے جو سب سے آخری سورتوں میں شمار کی جاتی ہے.پس جبکہ یہی آیت بعینہٖ مدنی سورتوں میں بھی ہے جس زمانہ میں کئی دوسری چیزوں کے استعمال سے روکاجاچکاتھا تویہ تاویل بھی درست نہیں ہوسکتی.اب رہا ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہا ہے کہ یہی چیزیں حرام ہیں کوئی اَورچیز حرام نہیں.سومیرے نزدیک ان کی بات درست ہے کیونکہ اس کے سوااَورکوئی معنے نہیں بن سکتے.جن لوگوں کایہ مذہب ہے ان میں سے ایک ابن عباس ؓہیں.ان کے متعلق بخاری میں جابر بن عبداللہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ان کا یہی مذہب تھا کہ یہی چار چیز یں حرام ہیں جو اس آیت میں بیان ہیں.
Page 235
اورابودائود کی روایت ہے کہ ابن عمر ؓ کا بھی یہی مذہب تھا.اس میں آتاہے کہ اَنَّہٗ سُئِلَ عَنْ اَکْلِ الْقُنْفُذِ فَتَلَا قُلْ لَّٓا اَجِدُ فِیْ مَآ اُوْحِیَ اِلَیَّ الآیۃ(سنن ابوداؤد کتاب الاطعمۃ باب فی اکل حشرات الارض...) اورعائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ابن ابی حاتم نے اوربعض اَورلوگوں نے مسند صحیح سے بیان کیا ہے کہ اِنَّھَا کَانَتْ اِذَاسُئِلَتْ عَنْ اَکْلِ کُلِّ ذِیْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ قالتْ قُلْ لَّآ اَجِدُ فِیْ مَآاُوْحِیَ اِلَیَّ الآیۃ.(روح المعانی سورۃ الانعام زیر آیت ۱۴۳ تا ۱۴۷) اسی طرح ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے بھی روایت کی ہے کہ قَالَ لَیْسَ مِنَ الدَّوَابِّ شَیْءٌ حَرَامٌ اِلَّا مَاحَرَّمَ اللہُ تَعَالیٰ فِی کِتَابِہٖ قُلْ لَّآاَجِدُ.امام مالکؓ کابھی یہی مذہب تھا.(روح المعانی زیر آیت سور ۃ انعام زیر آیات ۱۴۳ تا ۱۴۷) اب سوال یہ ہے کہ کیاباقی سب چیزوں کا کھاناجائز ہے بعض ائمہ کایہ مذہب ہے کہ ان کے سواباقی سب اشیاء کاکھانا جائز ہے مگر میرے نزدیک باوجود ا س کے بعض اشیا ء کاکھانا ناجائز ہے.مگر ہم انہیں شریعت کی اصطلاح میں حرام نہیں کہہ سکتے.چنانچہ ابن ماجہ میں سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ؐ نے فرمایا.اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّ اللہُ فِیْ کِتَابِہِ وَالْـحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللہُ فِیْ کِتَابِہٖ(ابن ماجہ کتاب الاطعمۃ باب اکل الجبن والسمن) جو خدا تعالیٰ نے حرام کیا صرف وہی حرام ہوگا باقی اس کے تابع ہوں گے اس سے میں یہ نتیجہ نکالتاہوں کہ خدا تعالیٰ نے جن اشیاء کو حلا ل کیا ہے انہی کو ہم حلال کہہ سکتے ہیں اورجن کو حرام کہا ہے انہی کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں.باقی جو درمیانی چیز یں ہیں ان کے متعلق حکم حلال اورحرام کے تابع ہو گا.دلالۃ النص کے طور پر نہ ہو گا.سورۃ مائدہ میں بھی اشارۃً اس صداقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.وہاںفرمایا ہے اُحِلَّتْ لَکُمُ بَھِیْمَۃُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَایُتْلٰی عَلَیْکُمْ (المائدۃ :۲).چوپایوں میں سے تم پر انعام کی قسم کے بہائم حلال ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر حراموں میں کیاگیاہے.حرام کے مقابل پر حلال اشیاء انعام کی کئی قسمیں ہیں.اونٹ.بکری.مینڈہا.دنبہ.گائے.یہ حلال ہیں.اس کے بعد فرمایا کہ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ الْمَیْتَۃُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیْرِوَمَآاُھِلَّ لِغَیْرِاللّٰہِ بِہٖ (المائدۃ :۴) یعنی ان حلال چیز وں کے مقابل پر کچھ حرام بھی ہیں.اول مردہ خواہ حلال جانور کا ہو.دوسرے خون وہ بھی خواہ حلال جانورکاہو.تیسرے خنزیر کاگوشت.چوتھے جس پر خدا تعالیٰ کے سوادوسر ے معبودوں کانام بلند کیا گیا ہو خواہ وہ جانور حلال ہی کیوں نہ ہو ں پھر مردہ اورخون کی مزید تشریح کی گئی ہے اورفرمایا ہے.کہ نَطِیْحَۃُ.مَوْقُوْذَۃٌ وغیرہ
Page 236
حرام ہیں.یہ نئی حرمت نہیں بلکہ میتہ اوردم کی تشریح ہے.یہ سب کچھ بیان کرکےپھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے.یَسْئَلُوْنَکَ مَاذَٓااُحِلَّ لَھُمْ (المائدۃ :۵) کہ مسلمان پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیاکیا چیز یں حلا ل کی گئی ہیں ؟اب اگر اِنَّمَاحُرِّمَ عَلَیْکُمْ کے معنے یہ ہوتے کہ ان کے سواباقی سب چیز یں کھانی جائزہیں توجب قرآن کریم نے ان چارچیزوں کو اس سوال سے پہلے بیان کردیاتھا.یہ سوال دوبارہ کیوں کیاجاتا؟ حرام اورحلال چیزوں کے بیان کرنے کے بعد پھر اس سوال کوبیان کرنا اوراس کا جواب دینابتاتاہے کہ پہلی حلال چیزوں کی تشریح میں کچھ اغلاق ابھی باقی تھا جس کے متعلق صحابہ نے سوال کیا اوراللہ تعالیٰ نے بھی ان کے سوال کایہ جوا ب نہیں دیا کہ ابھی توہم بتاچکے ہیں پھر کیوں پوچھتے ہو.بلکہ سوال کی ضرورت تسلیم کرکے اس کا جوا ب دیا ہے.اوروہ جواب یہ دیا ہے کہ قُلْ اُحِلَّ لَکُمْ الطَّیِّبٰتُ (المائدۃ:۵)کہ باقی اشیاء میں سے جو طیّبات ہیں وہ حلا ل ہیں اورجو طیبات نہیں وہ حلا ل نہیں.اس سے معلو م ہواکہ سب حلال چیزیںطیب نہیں ہیں.جوطیب ہیں صرف ان کاکھا ناجائز ہے باقی کاکھا ناجائز نہیں.لیکن ان کانام حرام نہیں رکھ سکتے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کامضمون بیان فرمایا ہے.ایک حدیث میں آتاہے کہ اِنَّ الْـحَلَالَ بَیِّنٌ وَالْـحَرَامَ بَیِّنٌ وَبَیْنَھُمَا اُمُوْرٌ مُشْتَبِھَاتٌ لَایَعْلَمُھَا کَثِیْرٌ مِنَ النَّاسِ.(بخاری کتاب الایمان باب فضل من استبرأ لدینہ) یعنی حلال بھی بیان ہوچکے ہیں اورحرام بھی.پھر ان دونوں کے درمیان مشتبہ امور ہوتے ہیں.جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے.پس ان کے بارہ میں قیاس اورعلم طب اورتجربہ وغیرہ سے کام لے کر فیصلہ کیاجائے گا.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو ہر بادشاہ کی رکھ ہوتی ہے اوراللہ تعالیٰ کی رکھ اس کی محرمات ہیں.جس طرح ہوشیارچرواہارکھ کے پاس نہیں چراتا.تاایسانہ ہوکہ غفلت میں اس کے جانور اس میں چلے جائیں اوروہ سزاکامستحق ہوجائے.اسی طرح مومن محرمات کے ساتھ کے علاقہ میں اپنے نفس کو نہیں چراتاتاپکڑانہ جائے.اس روایت سے استنباط ہوتا ہے کہ حرام اشیاء سے ملتی جلتی اشیاء کوبھی گوحرام نہیں کہہ سکتے مگر ان سے بچنا تقویٰ کے لئے ضروری ہے.نئی اشیاء کے حلال وحرام کے پرکھنے کا ذریعہ اس اصول کے مطابق جو نئی نئی اشیا ء دنیا میں نکلتی رہتی ہیں ان کے متعلق یہی حکم ہو گاکہ ہم ان کا قیاس حرام اورحلال پر کریں.اگر حلال سے ان کی مشابہت زیادہ ہے توانہیں استعمال کریں.اگرحرام سے مشابہت زیادہ ہے توان سے اجتناب کریں.چنانچہ تازہ مثال اس قسم کی چیزوں کی
Page 237
تمباکو ہے.حضرت مسیح موعودعلیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ سے اس کے بارہ میں پوچھا گیاتوآپ نے فرمایایہ چیز بعد میں نکلی ہے مگر اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں.کہ اگررسول کریم صلعم کے زمانہ میں اس کارواج ہوتاتوحضورؐاس سے ضرورمنع فرماتے.(الحکم ۲۴ مارچ ۱۹۰۳ ء صفحہ ۷) اسلام کے نزدیک کھانے کی چیزوں کے کئی درجے اصل بات یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں کے متعلق اسلام نے کئی درجے بتائے ہیں.حرام.ممنوع.حلال.طیب.حرام وہ جسے قرآن نے حرام کیا.ممنوع جسے قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق رسول کریم صلعم نے منع فرمایا یابعد کی معلوم شدہ چیز جس کے متعلق تحقیقات کرکے مسلمان اسے ناپسندیدہ قراردے دیں.حلال اور طیب کے معنی حلال.وہ جو اپنی اصل وضع کے لحاظ سے طیب ہو.طیب.وہ جو اپنی موجودہ حالت میں بھی طیب ہو.یعنی ہروہ چیز جس کو کسی صورت میں بھی کھاناجائز ہے اس کو حلال کہیں گے.جیسے بکراحلال ہے.مگرچونکہ کچے گوشت کی صورت میں کھایا نہیںجاسکتا ہے اس لئے اس صورت میں طیب نہیںہوگا.لیکن اس کو پکاکے کھا نا طیب ہوگا.بہترین غذا طیب سے اتر کرحلال ہے.اس کے بعد اوراشیا ء ہیں وہ ممنوع ہیں.ان کاکھا نادرست نہیں.مثلاً ڈاکٹر ہیضہ کے دنوں میں کھیرے کاکھانامنع کردے توگوکھیراعام دنوں میں حلال اورطیب ہے مگر ان دنوں میں حلال تورہے گاطیب نہ رہے گا.جوچیزیں حرام کے بعد ہیں یعنی ممنوع ہیں ان کے متعلق بھی ہم کہیں گے کہ ان کاکھا نا درست نہیں.یعنی ان کے کھانے سے انسان نقصان اٹھائے گا.یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانور مختلف کاموں کے لئے پیداکئے ہیں.کوئی خوبصورتی کے لئے کہ دیکھنے میں خوبصور ت معلو م ہوتاہے.کوئی آواز کے لئے کہ اس کی آواز بہت عمدہ ہے.کوئی کھا نے کے لئے کہ اس کاگوشت اچھا ہے.کوئی دوائی کے لئے کہ اس کے گوشت میں کسی مرض سے صحت دینے کی طاقت ہے.صرف جانوراورحلال دیکھ کراسے نہیں کھاناچاہیے.ہوسکتا ہے کہ ایک جانورکا گوشت صحت کے لئے مضرنہ ہو مگروہ مثلاً بعض فصلوں یا انسانوں میں بیماری پیداکرنے والے کیڑوں کو کھاتاہوتوگوشت کے لحاظ سے اس کاگوشت حلال بھی ہوگااورطیب بھی.مگر پھر بھی بنی نوع انسان کاعام فائدہ دیکھتے ہوئے اس کاگوشت طیب نہ رہے گا.کیونکہ اس کے کھانے کی وجہ سے انسان بعض اورفوائدسے محروم رہ جائیں گے.حلال اور حرام کے سمجھنے کے متعلق ایک بچپن کا واقعہ مجھے بچپن ہی میں یہ سبق سکھایاگیاتھا.میں بچپن
Page 238
میں ایک دفعہ ایک طوطاشکارکرکے لایا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے دیکھ کر کہا محمود اس کاگوشت حرام تونہیں.مگراللہ تعالیٰ نے ہر جانور کھانے کے لئے ہی پیدا نہیں کیا.بعض خوبصورت جانور دیکھنے کے لئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر آنکھیں راحت پائیں.بعض جانوروں کو عمدہ آواز دی ہے کہ ان کی آوازسن کرکان لذت حاصل کریں.پس اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر حس کے لئے نعمتیں پیداکی ہیں وہ سب کی سب چھین کر زبان ہی کو نہ دے دینی چاہئیں.دیکھو یہ طوطاکیساخوبصور ت جانور ہے.درخت پربیٹھا ہوادیکھنے والوں کوکیسابھلا معلوم ہوتاہوگا.طیب میں یہ بھی شرط ہے کہ دوسری مخلوق کا حق نہ مارا جائے غرض طیب کے لئے جہاں صحت کے لحاظ سے اچھا ہوناشرط ہے وہاں اس کے کھانے میںیہ بھی شرط ہے کہ اس چیز کے کھانے سے انسا ن کے دوسرے حواس یا دوسرے بنی نوع انسا ن یادوسری مخلوق کا حق نہ ماراجائے.بلکہ دوسروں کے جذبات کو مدنظررکھنا بھی ضروری ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَااسْتَخْبَثَتْہُ الْعَرَبُ فَھُوْ حَرَامٌ(روح المعانی سورۃالانعام زیر آیت ۱۴۳ تا ۱۴۷)یعنی جسے عر ب خراب کھاناسمجھیں وہ حرام ہے.یہاں حرام کے معنے یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کاکھانے والا گنہگار ہوتا ہے.بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ عربوں کے سامنے اسے نہیں کھاناچاہیے کیونکہ اس طرح آپس کے تعلقات کشیدہ ہوجاتے ہیں.اس وقت ہندوستا ن میں گائے کاگوشت بھی ایسا ہی ہے.جملہ مسلمانوں کو نصیحت مسلمانوں کو احتیاط چاہیے کہ گائے کاگوشت ہندوئوں کے سامنے نہ کھایاکریں اوراس کا ذکر بھی ان کے سامنے نہ کیا کریں.کیونکہ اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے.وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ اوراپنی زبانوںکے جھوٹے بیان کے سبب سے (یہ)مت کہوکہ یہ حلال ہے اوریہ حرام ہے (تاایسانہ ہو)کہ تم هٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ١ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اللہ(تعالیٰ )پر جھوٹ باندھنے والے بن جائو.جولوگ اللہ(تعالیٰ)پرجھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز
Page 239
يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَؕ۰۰۱۱۷ کامیاب نہیں ہوتے.حلّ لُغَات.تَصِفُ.تَصِفُ وَصَفَ سے مضارع واحد مؤنث غائب کاصیغہ ہے.اور وَصَفَ کے لئے دیکھو نحل آیت نمبر ۶۳.یُفْلِحُوْنَ.یُفْلِحُوْنَ اَفْلَحَ سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.اوراَفْلَحَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں فَازَ وَظَفِرَ بِمَا طَلَبَ.وہ اپنے مطلوب کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا.اَفْلَحَ زَیدٌ:نَجَعَ فِیْ سَعْیِہٖ وَاَصَابَ فِیْ عَمَلِہٖ.اپنی کوشش میں کامیاب ہوگیا اورحسب خواہش مطلوب کو پالیا (اقرب)پس لَایُفْلِحُوْن کے معنے ہوں گے وہ کامیاب نہیں ہوتے.تفسیر.لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ میں یاتومَا مصدر یہ ہے اورلَاتَقُوْلُوْا کامفعول اَلْکَذِب ہے یعنی اپنی زبانوں کے بولے ہوئے جھوٹ کی بناء پر یہ نہ کہو کہ فلاںچیز حلال ہے اورفلاں حرام ہے.یاپھر مَا موصولہ ہے جس کے روسے معنےیہ ہوں گے کہ جن چیزوں کو تمہاری زبانیں جھوٹ بول کر حلال حرام قراردیتی ہیں ان کی نسبت یہ نہ کہو کہ وہ حلا ل ہیں یاحرام.تمہاری زبان سے مراد دونوں صورتوں میں قو م کے سرداروں کی زبانوں سے ہے کیونکہ ساری قوم جھوٹ نہیں بنایاکرتی.بعض لیڈر جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں.لِتَفْتَرُوْا میں لام عاقبت ہے لِتَفْتَرُوْا عَلَی اللہِ الْکَذِبَ.یہاں پر لام عاقبت کے معنے دیتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایسانہ کہو کیو نکہ اس کانتیجہ یہ ہو گاکہ تم اللہ پر افتراءکر نے لگ جائو گے یعنی اس طرح اپنے پاس سے حلال حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ پر افتراء کے مترادف ہے کیونکہ حلال حرام مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کاکام ہے.اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ مفتری کامیاب نہیں ہوتے.یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے.مگر مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں.خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ماموروں کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہے.
Page 240
مَتَاعٌ قَلِيْلٌ١۪ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۰۰۱۱۸ (یہ دنیا )تھوڑاساعارضی سامان ہے.اور(اس کے نتیجہ میں )ان کے لئے دردناک عذاب (مقدر)ہے.تفسیر.یعنی چند دن تک اگر عذاب سے بچ جائیں تواَوربات ہے مگر لمبی عمر نہیں پاتے.یعنی اتناعرصہ الہام شائع کرنے کے بعد نہیں پاتے جتنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوملا.وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ اورجن لوگوں نے یہودی مذہب اختیار کیا تھا ان پر (بھی)ہم نے اس سے پہلے وہ (تمام )چیزیں حرام کی تھیں جن قَبْلُ١ۚ وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ کا ذکر ہم نے تجھ سے کیاہے.اورہم نے ان پر (یہ احکام دےکر )ظلم نہیں کیاتھا بلکہ وہ (ان احکام کوتوڑ کر)اپنی يَظْلِمُوْنَ۰۰۱۱۹ جانوں پر ظلم کیاکرتے تھے.حلّ لُغَات.قَصَصْنَا قَصَصْنَا قَصَّ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے.اورقَصَّ کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۴.قَصَّ یَقُصُّ قَصًّا وقَصَصًا اَثْرَہُ: تَتَبَّعَہٗ شَیْئًا بَعْدَ شیْءٍ.اس کا نشان تلاش کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا.وَمِنْہُ فَارْتَدَّا عَلٰی اٰثَارِھِمَا قَصَصًا.اَیْ رَجَعَا فِی الطَّرِیْقِ الَّتِیْ سَلَکَا ھَا یَقُصَّانِ اَلْإِثْرَ.اور انہی معنوں میں قرآن کریم کی آیت فَارْتَدَّاعَلَی اٰثَارِھِمَا قَصَصًا.میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.قَصَّ عَلَیْہ الْخَبْرَ وَالرُّؤْیَا:حَدَّثَ بِھِمَا عَلٰی وَجْھِھِمَا بات کو بے کم و کاست بیان کیا.ٹھیک طور پر بیان کیا.وَمِنْہُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ.اَیْ نُبَیِّنُ لَکَ اَحْسَنَ الْبَیَانِ.اور انہی معنوں میں سورہ یوسف کی آیت نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ میں یہ لفظ آیا ہے.یعنی ہم تیرے سامنے ٹھیک ٹھیک بات بیان کرتے ہیں.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں بتایاہے کہ کفارکی طرح یہودیوں نے بھی ایساکیاتھاجس کے بدلہ میں ان کوسزاملی
Page 241
تھی.اگرتم بھی کروگے توتمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا.اس آیت میں مِنْ قَبْلُ کے لفظ سے مراد مِنْ قَبْلُ کے متعلق مفسرین میں بہت اختلاف ہواہے کہ اس سے کیا مراد ہے.بعضوں نے مِنْ قَبْلُسے مراد سورۃ انعام لی ہے.وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سورۃ انعام میں ان محرمات کا ذکر آچکا ہے.اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے (مجمع البیان زیر آیت ھذا).لیکن یہ غلط ہے.وہاں بھی یہ الفاظ ہیں قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ(الانعام :۱۴۶)یعنی کفارسے کہہ دے کہ میں تواپنے اوپر نازل ہونے والی وحی میں سوائے فلاں فلاں چیز کے اَورکوئی چیز حرام نہیں پاتا.ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ سورۃ انعام سے بھی پہلے یہ حکم نازل ہوچکاتھا.چار حرام چیزوں کا ذکر چار سورتوں میں اب مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ان چار حرام چیزوںکا ذکرصرف چارسورتوں میں ہے.بقرہ میں جو مدینہ میں نازل ہوئی.مائدہ میں جو نہ صر ف مدینہ میں نازل ہوئی بلکہ اس کے آخری ایام میں نازل ہوئی (تفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت ھذا).نحل میں کہ جہاں کہا ہے کہ یہ حکممِنْ قَبْلُ نازل ہوچکا ہے.اورانعام میں کہ وہاں بھی یہی اشارہ کیاگیا ہے کہ اس سے پہلے یہ حکم نازل ہوچکا ہے.پس آپس میں ایک دوسری کی طرف اشارہ سمجھانہیں جاسکتا.کیونکہ دونوں سورتیں ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہوسکتیں.اوران دونوں کے علاوہ کسی اورمکی سور ۃ میں یہ ذکر ہے نہیں.مفسرین نے یاتو اس عقدہ کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی یا اکثر ایسے جواب دیئے ہیں جومعقول نہیں.مثلاً بعض نے سورۃ مائدہ کی طر ف اشارہ قرار دیا ہے جودرست نہیں.کیونکہ سورۃ مائدہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے(تفسیر کبیر لامام رازی سورۃ الانعام :۱۲۰).رازی نے یہ جواب دیا ہے کہ سورۃ انعام ہی سب سے پہلی سورۃ ہے جس میں یہ ذکر ہے.اوراس کی آیت قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَّاحُرِّمَ عَلَیْکُمْ میں اس کے بعد آنےوالی آیت قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا کی طرف اشارہ ہے (تفسیر کبیر لامام رازی سورۃ الانعام آیت۱۴۶).اوراتنے تھوڑے فاصلہ کی بناء پر اگلی آیات کی طرف اشارہ کرنے میں کوئی حرج نہیں.اما م رازی کایہ جوا ب ہرگز درست نہیں ہوسکتا.کیونکہ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ سے بعد کی آیت کی طرف تواشارہ ہویا نہ ہو.مگر جس آیت کی طرف و ہ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی تویہی کہتی ہے کہ قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ جس کے معنے یہ ہیں کہ اس آیت سے بھی پہلے کوئی اورآیت موجود ہے جس میں یہ مسئلہ بیان ہواہے.پس یہ جواب بھی مشکل کوحل نہیں کرتا.
Page 242
مصنف فتح الباری نے اس کاایک عجیب جواب دیا ہے جومیرے نزدیک قابل قدر ہے.اورمیں سمجھتا ہوں کہ اگر اس مشکل کاکوئی اَورحل موجود نہ ہوتا تویقیناًیہی جواب صحیح ہوتا.وہ لکھتے ہیں کہ اس کااشارہ سور ۃ مائدہ کی طرف ہے اورگومائدہ نزول کے لحاظ سے انعام سے بعد کی ہے.لیکن چونکہ علم الٰہی میں سورۃ مائدہ کوآخری ترتیب میں پہلے رکھناتھا.اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے نازل ہونے والی سورۃ میں اس بعد میںرکھی جانے والی سورۃ کی طرف اشارہ کردیااوراس طرح ایک ثبوت مہیا کردیا کہ قرآن کریم کی ترتیب الہا می ہے.ان کا یہ جوا ب نہایت لطیف ہے اوربعض دوسرے مقامات کے حل کرنے کے وقت مدنظر رکھنے کے قابل ہے.اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب قرآن میں پہلے نازل ہونے والی سورتو ںمیں بعد میں نازل ہونے والی سورتوں کے مضامین کو واضح کیا گیا ہے.جیسا کہ سورئہ نحل کے بعض مسائل کو سورۃ اسراء میں حل کیاگیا ہے حالانکہ سورۃ اسراء پہلے کی ہے اورسورۃ نحل بعد کی ہے اوریہ قرآن کے علمی کمالات میں سے معجزانہ کمال ہے.باوجود اس جواب کو لطیف سمجھنے کے میرے نزدیک اس موقعہ پر اس جواب کی ضرورت نہیں کیونکہ ا س کا جواب ترتیب نزول کو مدنظررکھتے ہو ئے بھی موجود ہے.قرآن کریم سے یہ توثابت ہے کہ سورۃ نحل سورۃ انعام سے پہلے نازل ہوئی ہے کیونکہ سورۃ انعام میں دوجگہ اس کے مضمو ن کی طرف اشار ہ کیا گیا ہے.ایک انعام کے چودہویں رکوع میں جس میں فرمایا ہے قَدْفَصَّلَ لَکُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَیْکُمْ اِلَّا مَّااضْطُرِرْتُمْ اِلَیْہِ(الانعام :۱۲۰) اور دوسرے آیت قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ (الانعام :۱۴۶)اورتاریخ سے بھی یہ امر ثابت ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اسراء کے واقعہ کے بعد جو ہجر ت سے صرف چھ ماہ یاایک سال پہلے ہواتھا(الطبقات الکبری لابن سعد ذکر معراج ).حرام حلال کے احکام نازل ہوئے ہیں اوریہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ سورۃ انعام ایک ہی دفعہ سب کی سب نازل ہوئی تھی ٹکڑے ٹکڑے کرکے نازل نہیں ہوئی(الاتقان).پس معلوم ہواکہ سورۃ نحل کے بعد ہی یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اوراسی کی آیت کی طرف اس میں اشارہ ہے.اب ر ہ گیا یہ سوال کہ آیت زیر بحث میں جو مِنْ قَبْلُ کے الفاظ ہیں ان سے کیا مراد ہے ؟تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر بالکل سادہ ہے.مگر نامعلوم مفسرین کاذہن ادھر کیوں نہیں گیا.بات یہ ہے کہمِنْ قَبْلُ سے مراد کوئی پہلی نازل شدہ سورۃ نہیں بلکہ اسی سورۃ کی پہلی نازل شدہ آیت ہے چنانچہ اس آیت سے دوآیتیں پہلے اِنَّمَاحَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۃَ (النحل:۱۱۶)والی آیت موجود ہے اسی کی طرفمِنْ قَبْلُ کا اشارہ ہے مِنْ قَبْلُ میں سال یادوسا ل کی شرط نہیں.ہم عام طور پر تصنیف میں جو با ت
Page 243
پہلے لکھی گئی ہو اس کی نسبت کہتے ہیں کہ ’’میں پہلے لکھ چکاہوں ‘‘.اس سے مراد کوئی دوسری کتاب نہیں ہوتی بلکہ ان الفاظ سے پہلے کی کوئی عبارت مراد ہوتی ہے.اسی رنگ میں یہ الفاظ اس آیت میں مستعمل ہوئے ہیں.بنی اسرائیل کے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کی تشریح یہ جو فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوںپر ظلم کیا.اس سے یہ مراد ہے کہ بعض اورچیز یں بھی یہود کے لئے ممنوع قرار دی گئی تھیںجیسے گائے اوربکری کی چربی.پس اس کی طرف یہاں اشارہ کیاگیاہے اوربتایا ہے کہ یہ حرمت حقیقی نہ تھی بلکہ ان کے ظلمو ں کی وجہ سے تھی.چنانچہ سورئہ انعام میں اس مضمون کو وضاحت سے بیان فرمایاگیاہے فرماتا ہے وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَاۤ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَاۤ اَوِ الْحَوَايَاۤ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ١ؕ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (الانعام:۱۴۷)یعنی یہود پر گائے اوربکری کی چربی بھی حرام کی گئی تھی سوائے اس چربی کے جو پیٹھ پرہویا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو یاہڈی کے اوپر لگی ہوئی ہو.مگر یہ حرمت ان کی سرکشیوں کی سزاطور پر جاری کی گئی تھی مستقل حرمت نہ تھی.ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا پھر (یاد رکھو کہ)جن لوگوں نے بے خبری کی حالت میں (کوئی )برائی کی ہو (اور)پھر اس کے بعد(اس سے )توبہ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْۤا١ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ کرلیں اور(اپنی غلطی کی)اصلاح (بھی )کریں ان کے حق میں تیرارب ان (شرائط کے پوراکرنے)کے بعد رَّحِيْمٌؒ۰۰۱۲۰ بہت ہی بخشنے والا (اور)باربار رحم کرنے والا (ثابت)ہوگا.حلّ لُغَات.اَلسُّوْءُ اَلسُّوْءُکے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۵۴.اَلسُّوْءُ کُلُّ مَا یَغُمُّ الْاِنْسَانَ مِنَ الْاُمُوْرِ الدُّنْیَوِیَّۃِ وَالْاُخْرَوِیَّۃِ وَمِنَ الْاَحْوَالِ النَّفْسِیَّۃِ وَالْبَدَنِیَّۃِ وَالْخَارِجَۃِ مِنْ فَوَاتِ مَالٍ وَجَاہٍ وَفَقْدِ حَمِیْمٍ.دنیوی و اخروی معاملات اور نفسی و بدنی حالات یا ان کے علاوہ اور خارجی واقعات یعنی مال و عزت کے کھوئے جانے یا دوست و احباب کی علیحدگی کی وجہ سے جو امور انسان کو اندوہگین بنائیں ان سب کو سوء کے نام سے موسوم کرتے ہیں.(مفردات)
Page 244
جَھَالَۃ جَھَالَۃٌ جَھِلَ کامصدر ہے اورجَھِلَہٗ کے معنے ہیں ضِدُّ عَلِمَہُ اس سے ناواقف اوربے خبررہا.نیز اَلْجَہَالَۃُ کے معنی ہیں ضِدُّ العِلْمِ وَالْمَعْرِفَۃِ.بے علمی اوربے خبر ی.(اقرب) تفسیر.اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایاتھاکہ یہود نے نافرمانی کی اس لئے ان پر تکالیف آئیں جیسے فرمایا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ کہ وہ ظلم کرتے تھے اس لئے اس کانتیجہ انہیں دکھ ملا.اب فرمایا ہے کہ گو یہود نے غلطیاں کیں.لیکن اگروہ اب بھی توبہ کریں تو خدا تعالیٰ کو بخشنے والامہربان پائیںگے.اس میں یہود کاکوئی خاص لحاظ نہیں بلکہ یہ عام قانون کے مطابق ہے.ظاہر ہے کہ اولاد کی تکالیف کا ماں باپ پر اثر پڑتا ہے جس طرح بچوں کے بیمار ہونے سے ماں باپ کوتکلیف ہوتی ہے اسی طرح ان کے دوزخ میں پڑنے سے ماں باپ کو تکلیف ہو گی.چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتاہے کہ قیامت کے دن بعض ظاہر میں صحابی نظر آنے والے لوگوں کو دوزخ میں جاتے دیکھیں گے توفرمائیں گے اُصَیْحَابِیْ.اُصَیْحَابِیْ (بخاری کتاب التفسیر باب و کنت علیھم شھیدًا)پس اس تکلیف سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ بزرگوں کی اولادسے نیکی کاسلوک کرتا ہے اوران بزرگوں کو تکلیف سے بچانے کے لئے ان کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلْـحَقْنَابِھِمْ ذُرِّیَّـتَھُمْ کہ ہم مومنوں کی اولاد کو اگر وہ مومن ہو ں گے جنت میں ان کے ساتھ ملادیں گے خواہ اولاد کادرجہ کم ہی کیوں نہ ہو.اس لئے انبیاء و صلحاء کی امتوں اورجماعتوں کے لئے بار بار قرآن کریم میں وعدے ہیں.کہ ان پر خاص فضل ہوگاتاان کے دکھ پانے سے انبیاء اورصلحاء کو تکلیف نہ ہو.اورچو نکہ قرآن کریم سے معلو م ہوتاہے کہ سب قومو ں کی طرف انبیاء آئے ہیں اس لئے ساری دنیا ہی اس فضل میں حصہ دار ہے اوریہود کی خصوصیت نہیں.ثُمَّ اِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِیْنَ عَمِلُواالسُّوْٓءَ بِجَھَالَۃٍ.جہالت علم کے مقابل کالفظ ہے اوراس کے معنے ناواقفیت کے ہیں لغت میں ہے اَلْجَھَالَۃُ ضِدُّ الْعِلْمِ.اسی طرح لکھا ہے اَلْجَہَالَۃُ ضِدُّ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَۃِ یعنی جہالت علم کاضد ہے اورجہالت کے معنے عدم علم اورعدم معرفت کے ہیں.اس جگہ عدم علم کے معنے نہیں کیونکہ جسے علم نہ ہو اسے سزانہیں ملتی بلکہ عدم معرت کے ہیں یعنی علم توحکم کاہو لیکن تقویٰ میں کمزوری کی وجہ سے یہ شخص وقت پر اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکے.ایسا شخص سزاکامستحق ہوتاہے کیونکہ علم کے بعد تقویٰ کے حصول کی کوشش نہ کر ناایک دانستہ گناہ ہے.درحقیقت معرفت ہی ہے جوانسان کو گنا ہ سے بچاتی ہے.جولوگ ظاہر ی علم کو کافی سمجھتے ہیں وہ آخر گنا ہ میں
Page 245
ملوث ہوکر رہتے ہیں.پس انسان کو معرفت اورخشیت الٰہی میں ترقی کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے.جہالت کی دو اقسام یہ بھی یاد رکھنا چاہیےکہ جہالت دو قسم کی ہوتی ہے ایک دائمی جس کاشکار عرفان سے بالکل محروم ہوتاہے اورگناہ میں ہی اُسےسب لذت ملتی ہے.دوسری وقتی.اس کا شکار ادنیٰ عارف بھی ہوجاتا ہے کیونکہ بعض وقت اس کے عرفا ن کادرجہ کم ہوتاہے تواس وقت و ہ نفسانی جذبات کا شکار ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے لَایَزْنِی الزَّانِیْ حِیْنَ یَزْنِیْ وَھُوَ مُوْمِنٌ فَیَخْرُجُ مِنْہُ الْاِیْمَانُ فَیَصِیْرُ عَلَی رَأْسِہِ کَالظُّلَّۃِ الخ یعنی جب زانی زناکررہاہوتاہے تواس وقت اس کے قلب کی حالت مومنانہ نہیں ہوتی اوراس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سرپرچھاتے کی طرح منڈلاتارہتاہے.(ترمذی ابواب الایمان باب لا یزنی الزانی)آخری فقرہ کے معنے بعض شراحِ احادیث نے یہ کئے ہیں کہ وہ ایمان اس وقت اس شخص کی سفار ش کررہاہوتا ہے.اَصْلَحُوْا کے دو معانی وَاَصْلَحُوْا.اپنی اصلاح کرلیں یادوسروں کی اصلاح کریں دونوںہی معنے ہوسکتے ہیں.اس میں یہ بتایاگیا ہے کہ گناہ کے بعدانسان کوصرف قلبی توبہ ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ جن وجوہ سے و ہ گناہ سرزد ہواتھا ان کو بھی دور کرنا چاہیے.تاکہ آئندہ گناہ سرزد نہ ہوسکے.اور’’دوسروں کی اصلاح کریں ‘‘سے اس طرف اشارہ ہے کہ اپنے گناہ کے کفارہ کے طور پر انہیں دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے.تاکہ ان کے ثواب میں جن کو وہ ہدایت کی طرف لائے ہوں شامل ہوجائیں.اورسابق گنا ہ کی وجہ سے جو اعمال میں کمی ہوجائے پوری ہوجائے.اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا١ؕ وَ لَمْ يَكُ ابراہیم یقیناہر(اک )خیرکاجامع.اللہ (تعالیٰ)کے لئے تذلل اختیارکرنے والا (اور)ہمیشہ خدا کی کامل مِنَ الْمُشْرِكِيْنَۙ۰۰۱۲۱ فرمانبرداری کرنے والاتھا.اوروہ مشرکوں میں سے نہیں تھا.حلّ لُغَات.اَ لْاُمَّۃُ اَ لْاُمَّۃُکے معنے ہیں.اَلْاِمَامُ.امام اَلرَّجُلُ الَّذِیْ لَانَظِیْرَ لَہُ.ایساآدمی جس کاکوئی نظیر نہ ہو.مُعَلِّمُ الْخَیْرِ.نیکی کی تعلیم دینے والانیز الْجَامِعُ لِلْخَیْرِ.خیر کاجامع.(تاج)پس اِنَّ اِبْرَاھِیْمَ کَانَ اُمَّۃً کے معنی ہوں گے کہ ابراہیم یقیناً ہرایک خیر کاجامع،نیکی کی تعلیم دینے والاامام،اوربے نظیر شخص تھا.
Page 246
قَانِتًا قَانِتٌ.قنَتَ سے اسم فاعل ہے اورقَنَتَ (یَقْنُتُ قُنْوَتًا)کے معنے ہیں اَطَاعَ.اطاعت کی اورقَنَتَ اللہَ وَقَنَتَ لِلہِ کے معنے ہیں ذَلَّ اللہ تعالیٰ کے حضور تذلل اختیار کیا نیز اس کے معنے ہیں.دَعا.اس نے دعاکی.قَامَ فِی الصَّلٰوۃِ.نماز شروع کی.اَمْسَکَ عَنِ الْکَلَامِ.کلام کرنے سے رکار ہا.نیز اَلْقَانِتُ کے معنے ہیں اَلْقَائِمُ بِالطَّاعَۃِ الدَّائِمِ عَلَیْھَا پوری طرح اطاعت کرنے والا.اَلمُصَلِّی.نماز گزار.(اقرب) الحنیف اَلْـحَنِیْفُ:اَلصَّحِیْحُ الْمَیْلُ اِلی الْاِسْلَامِ الثَّابِتُ عَلَیْہِ.اسلام کی طرف صحیح میلان رکھنے والا اوراس پر قائم رہنے والا.اَلْمَائِلُ عَنْ دِیْنٍ اِلَی دِیْنٍ.ایک دین کو چھو ڑکر دوسرے دین کی طرف جانے والا.اَلْمُسْلِمُ.کامل فرمانبردار.اس کی جمع حُنَفَاءُ آتی ہے.(اقرب) تفسیر.حضرت ابراہیم ؑ کو امت کہنے کی تشریح اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے اس کے ایک تویہ معنے ہیں کہ وہ نیکی کی تعلیم دینے والا اورسب قسم کی خیر کاجامع تھا.دوسرے میرے نزدیک ادھر بھی اشار ہ ہے کہ اس کے اندر وہ طاقتیں موجود تھیں جن سے امتیں پیداہوتی ہیں.حتی کہ ان طاقتوں کی وجہ سے اسے امت کہاجاسکتاہے گویا وہ درختِ امت کے لئے بطور بیج کے تھا.حضرت ابراہیم ؑ کی صفات کا بیان اس آیت میں حضرت ابراہیم کی بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں.ایک تویہ کہ وہ معلم خیر تھے.دنیا کو نیکی کی تعلیم دیتے تھے.دوسرے یہ کہ وہ جامع الخیر تھے.سب قسم کے اخلاق فاضلہ ان میں پائے جاتے تھے.تیسرے یہ کہ و ہ نہایت اعلیٰ فطرت رکھتے تھے جوزبردست نموکی قوتیں پوشیدہ رکھتی تھی.جس سے امتوں کاپیداہوناممکن تھا.چوتھے یہ کہ وہ قانت تھے.اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے.دعائیں کرنے والے تھے.پانچویں یہ کہ وہ حنیف تھے یعنی زبردست قوۃ مقاومۃ رکھتے تھے اور کبھی حق کے راستہ سے دوسری طرف مائل نہ ہوتے تھے.چھٹے یہ کہ وہ مشرک نہ تھے یعنی توحید پر کامل طور پر قائم تھے.یہ کامل توحید کے معنے اس سے نکلتے ہیں کہ قَانِتًا لِلہِ اورحَنِیْفًا کے بعد یہ فقرہ رکھا گیا ہے.جس سے معلوم ہوتاہے کہ اس جگہ عام موحد مراد نہیں.بات یہ ہے کہ عام طور پر انسان جب اس کے اند رخوبیاں پیداہوجائیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگ جاتاہے اوراس میں کبر اورخودبینی و خودرائی و خودستائی پیداہوجاتی ہیں اوروہ اپنے آپ کو بڑاسمجھنے لگ جاتاہے.یہ بھی ایک قسم کا شرک ہےاللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے متعلق یہ فرماکر کہ لم یک من المشرکین یہ بتایا ہے کہ باوجود اتنی خوبیوں کے وہ خداہی کابندہ رہا اوراپنے نفس کی خوبیوں کو اپنی طرف منسو ب کرکے شرک کامرتکب کبھی نہیں ہوا.
Page 247
شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ١ؕ اِجْتَبٰىهُ وَ هَدٰىهُ اِلٰى صِرَاطٍ (وہ)اس کے انعاموں کاشکرگزار تھا.اس (کے رب)نے اسے برگزیدہ کیااورایک سیدھی راہ کی طرف مُّسْتَقِيْمٍ۰۰۱۲۲ اس کی راہنمائی کی.حلّ لُغَات.اجتبَاہُ اِجْتَبَاہُ کے معنے ہیں :اِخْتَارَہُ وَ اصْطَفَاہُ اس کو چن لیا اور برگزیدہ کیا (اقرب) تفسیر.یعنی وہ اپنی ہرایک خوبی کو نعمت الٰہی سمجھتاتھا اوروہ ان تمام صفات کو خدا تعالیٰ کادیا ہواخزانہ قرار دیتاتھا.پس چونکہ وہ تمام نعمتوںکو خداہی کی عطا سمجھتا تھا.اس لئے جس قدرزیادہ اس کی خوبیاں نکھرتی تھیں اسی قدر وہ اپنے شکر اورانابت الی اللہ میں بڑھتاتھا.جب انسان میں یہ باتیں ہو ںتوپھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس کو اپنے فضل کے لئے چن لیتا ہے چنانچہ فرمایا تب ان نیکیوں کے بدلے میں مَیں نے اس کو پسند کرلیا اوراس کو ہرخوبی سے متصف پاکر اپنابرگزیدہ بنالیاتھا.اوراس کو ایسے راہ پر ڈ ال دیا جومستقیم تھی.یعنی خداتک پہنچانے والی تھی.مُسْتَقِیْمٍ کے لفظ میں اس طر ف اشارہ ہے.کہ وہ خدا تعالیٰ تک پہنچانے والی راہ تھی کیونکہ مستقیم راستہ وہی ہوتا ہے جو دونقطوں کے درمیا ن ہو.اوردین کے معاملہ میں ایک نقطہ انسان ہے اوردوسرانقطہ خداہے.پس جو راستہ خدا تعالیٰ تک پہنچائے وہی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ہوگا.اورجو راہ خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچاتا وہ مستقیم کہلا ہی نہیں سکتا.کیونکہ اس کارخ اس نقطہ سے ہٹ گیا جس کی طرف پہنچنا مقصود تھا.اس آیت کاتعلق پہلی آیات سے یہ ہے کہ پہلے بتایاجاچکا ہے کہ تم کوبھی انعام ملیں گے تم مکہ والوں کی طرح نہ بن جانا.جنہوں نے شریعت ہی کاانکار کردیا.اوراپنے لئے خود ساختہ قانون کافی سمجھا.اور تم یہود کی طرح بھی نہ بننا.جنہوں نے خدائی شریعت میں اختلافات شروع کردئے.اوراس کی خلا ف ورزی کرنے لگ گئے.اب بتاتاہے کہ تم کیسے بننا.فرمایا تم ابراہیم ؑ کی طرح بننا.جواوصاف اس کے ہیں وہ اپنے اندر پیداکرنا.اس کانتیجہ یہ ہوگا کہ جو سلوک ہم نے ابراہیم ؑ کے ساتھ کیاتھا وہی تمہار ے ساتھ کریں گے.وہ سلوک کیاتھا ؟اگلی آیت میں بیان کیاگیا ہے.
Page 248
وَ اٰتَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً١ؕ وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ اورہم نے اسے دنیا میں (بھی بڑی)کامیابی بخشی تھی.اوروہ آخر ت میں(بھی) الصّٰلِحِيْنَؕ۰۰۱۲۳ یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوگا.تفسیر.ان صفات کی وجہ سے ہم نے ابراہیمؑ کو دنیا میں بھی بڑی ترقیات دی تھیں.اورا س کو دنیا میں آرام کی زندگی عطا کی تھی اورآخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا.مِنَ الصّٰلِحِيْنَکا مطلب مِنَ الصّٰلِحِيْنَسے مراد جیساکہ میں پہلے بتاچکاہو ں (نحل رکوع ۱۲)یہ ہے کہ اس کی طاقتیں مرنے کے بعد اگلے جہان کی اعلیٰ ترقیات سے کامل مناسبت رکھنے والی ہوں گی.یعنی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انعامات پانے اوران سے فائد ہ اٹھانے کی قابلیت رکھتاہوگا.حضرت ابراہیم ؑ کی دنیوی ترقی اس آیت میں جہاں یہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعامات ہم نے دیئے تھے.وہاں اس سے یہ ظاہر کرنابھی مقصود ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیمؑ کے لئے توبگڑنے کاموقعہ ہی نہ تھا.کیونکہ وہ دنیاوی ترقیات سے محروم تھا.فرماتا ہےاگر کوئی یہ کہے تو یہ غلط ہوگا.ہم نے اسے دنیو ی ترقیات بھی دی تھیں (چنانچہ بائیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود دوسرے ملک سے ہجرت کر کے آنے کے حضرت ابراہیمؑ کی مالی حالت بھی بہت اعلیٰ ہوگئی تھی اورحکومت بھی حاصل ہوگئی تھی.پیدائش باب ۱۳آیت ۲،۱۴تا۱۶) مگر باوجود اس کے وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہے.پس اے مسلمانو !جب تم کو بادشاہت ملے توابراہیم کی طرح تما م ترقیات کو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اورامانتیں سمجھنا.اورمغرورنہ ہوجانا.
Page 249
ثُمَّ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا١ؕ وَ مَا اور(اے رسول)ہم نے تجھے وحی کے ذریعہ سے حکم دیا ہے کہ (ہماری )کامل فرمانبرداری پر ہمیشہ قائم رہنے والے كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۰۰۱۲۴ ابراہیم کے طریق کی پیروی کر اور(اے مکہ والو جانتے ہو کہ )وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا.حلّ لُغَات.مِلَّۃٌ مِلَّۃٌ کے معنوں کے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر ۱۴.اَلْمِلَّۃُ: اَلشَّرِیْعَۃُ اَوِالدِّیْنُ.شریعت اور دین کو ملت کہتے ہیں.وَقِیْلَ الْمِلَّۃُ وَالطَّرِیْقَۃُ سَوَاءٌ.بعض کہتے ہیں کہ ملت اور طریقہ ہم معنے لفظ ہیں.وَھِی اِسْمٌ مِنْ اَمْلَیْتُ الْکِتٰبَ ثُمَّ نُقِلَتْ اِلٰی اُصُوْلِ الشَّرَائِعِ بِاِعْتَبَارِ اَنَّہَا یُمْلِیْہَا النَّبِیُّ اور ملت اسم ہے جو اَمْلَیْتُ الْکِتَابَ کے محاورہ سے ماخوذ ہے پھر وہ شریعت کے اصول کے معنوں میں استعمال ہونے لگا.کیونکہ شریعت کے اصول نبی لکھاتا ہے.وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَی الْبَاطِلِ کَالْکُفْرِ مِلّۃٌ وَاحِدَۃٌ اور کبھی یہ لفظ جھوٹے مذہبوں پر بھی بولا جاتا ہے.جیسے اَلْکُفْرُ مِلَّۃٌ وَّاحِدَۃٌ کے محاورہ سے ظاہر ہے.وَلَاتُضَافُ اِلَی اللہِ وَلَا اِلٰی آحَادِ الْاُمَّۃِ.اور یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوتا.اور نہ امت کے کسی فرد کی طرف.یعنی دِیْنُ اللہِ تو کہہ سکتے ہیں مگر مِلَّۃُ اللہِ نہیں کہہ سکتے.اسی طرح قوم کی ملت کہیں گے زید یا بکر کی ملت کا لفظ نہیں بولیں گے.(اقرب) تفسیر.ترقیات کے موقعہ پر توکل اور ایمان رکھنے کی نصیحت اس آیت میں گویااس مضمون کو جومیں اوپر بیان کرآیاہوں خوداللہ تعالیٰ نے کھول کربیان فرما دیاہے اورمسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم ابراہیم کے طریق پر چلنا.اورپھر مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ کودہراکر اس طر ف اشار ہ کیا ہے کہ تم بھی ترقیات کے موقعہ پر خدا تعالیٰ کاتوکل اورا س پر ایمان نہ چھوڑنا.اس آیت سے بعض مسیحی یہ غلط استدلال کرتے ہیں کہ ا س آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضر ت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیمی دین ہی کے تابع تھے.حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں.بلکہ اس کامطلب صرف یہ ہے کہ جیسے اس نے کمال پیدا کیا اورشکر گزاری دکھا ئی ویسے ہی تم بھی کرو.یعنی تفصیلات میں اطاعت مراد نہیں بلکہ ان امور میں نقش قد م پر چلنے کی ہدایت دی گئی ہے جن کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے.اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ان امورپر چلنے
Page 250
کی ہرشخص کو ضرورت ہے اورآد م سے لے کر آخری انسان تک کوئی ان صفات سے مستغنی نہیں ہوسکتا.ابراہیم ؑ سے پہلے بھی جو لو گ خدارسیدہ تھے انہی صفات کے حامل تھے اورابراہیم بھی.ابراہیمؑ کانام خصوصاً اس لئے لیا گیاہے کہ مکہ کے لوگ ان کو اپنا باپ کہتے تھے (محاضرات تاریخ الامم الاسلامیۃ جلد ۱ صفحہ ۵۶)اوربا پ کی مثال دے کر غیرت دلانا اصلاح کا بہترین طریق ہے.سرولیم میور اس آیت پر لکھتاہے کہ محمدؐ صاحب پر اس جہالت کے زمانہ میں یہ علم منکشف ہوگیاتھا کہ خدا تعالیٰ کی رسالت اورنبوت تمام قوموں میں مسلسل طورپرجاری ہے (لائف آف محمد زیر عنوان گرینڈ کیتھولک فیتھ).(اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دشمن کے منہ سے بھی حق کہلوادیتا ہے ) اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ١ؕ وَ اِنَّ سبت(کاوبال)انہی لوگوں پرڈالاگیاتھا جنہوںنے اس میں اختلاف کیا تھا.اورتیرارب اس امر کے متعلق جس رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۰۰۱۲۵ میں وہ اختلاف کرتے تھے یقیناًقیامت کے دن فیصلہ کرے گا.حلّ لُغَات.اَلسَّبْتُ یہسَبَتَ(یَسْبِتُ) کامصدر ہے اورسَبَتَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں اِسْتَرَاحَ.اس نے آرام کیا.نیزاس کے معنے ہیں ہفتہ کاروز.(اقرب) تفسیر.سبت کے ذکر پر مفسرین کی حیرانگی اس جگہ مفسرین بہت حیران ہوئے ہیں کہ سورۃ النحل مکی ہے اس میں سبت کے ذکر کاکیاتعلق تھا.انگریز مفسرین نے ایک اورشگوفہ چھوڑاہے.وہ یہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتاہے کہ یہود کا ذکر اس آیت سے پہلے تھا مگر وہ آیت قرآن سے ضائع ہوگئی ہے اوریہ آیت رہ گئی ہے جس کی وجہ سے عبارت کاربط جاتا رہاہے.سبت کے ذکر کے متعلق مختلف مفسرین کا خیال بعض مفسرین نے کہا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو بھی نیکیوں کاحکم دیاگیاتھا.اس لئے ایک نیکی کے حکم اوراس کی خلاف ورزی کے انجام کا ذکر کرکے مسلمانوں کوڈرایا ہے تاوہ احتیاط رکھیں.بعض نے سبت کے لفظ سے سبت کے توڑنے کا عذاب مراد لیا ہے.یعنی وہ عذاب ان کے لئے تھاجنہوں
Page 251
نے اس میں اختلاف کیاتھا(کشاف زیر آیت ھذا).سبت ایک جدید مفسر نے اس جگہ سبت کے معنے قطع کے بھی کئے ہیں(بیان القرآن از چوہدری محمد علی صاحب زیر آیت ھذا).مگرا یسے موقعوں پر ان معنوں میں عر ب لوگ ہرگز ا س لفظ کو استعمال نہیں کرتے.سبت کے معنی وبال کے میرے نزدیک سبت کے وبال کے معنے ہی ٹھیک ہیں.قرآن مجید میں بھی اورعربی زبان میں بھی اس بات کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ مضاف حذف کرکے مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنادیتے ہیں.پس ’’جُعِلَ السَّبْتُ‘‘کے یہ معنے ہیں کہ سبت کااثر صرف ان لوگوں پر ہواتھا.(اور وہ یقیناًبرااثر تھا ) جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا.سورۃ بقرہ میں بھی ذکر ہوچکا ہے کہ سبت کی حرمت کو توڑنے کی وجہ سے یہود کو سزاملی تھی.سبت کے ذکر کا پہلی آیات سے تعلق اب یہ سوال بے شک پیدا ہوتا ہے کہ سبت کے ذکر کا پہلی آیات سے کیا ربط ہوا،تواس کا جواب یہ ہے کہ یہود میں نزول قرآن سے پہلے بھی یہ خیال تھا ،اورآج تک ہے کہ ہماری ساری تباہی اوربربادی صرف سبت کے توڑنے کی وجہ سے ہے.اوریہ کہ انہیں ہرگز ترقی نہ ملے گی جب تک وہ پھر سبت کی عزت کوقائم نہ کریں گے.آج بیسویں صدی میں بھی جبکہ مسلما ن جمعہ کی حرمت کو توڑ رہے ہیں.اورعیسائی اتوارکوچھوڑ رہے ہیں.یہودیوں میں ایسی سوسائٹیاں بن رہی ہیں جوسبت کی حرمت کو قائم کرنے کی تبلیغ کررہی ہیں فلسطین میں انہوںنے کئی گائوں میں اس کو جبراً قائم کرنا چاہا.جس کی وجہ سے وہاںکئی فسادات بھی ہوچکے ہیں.پس جب یہود کو کہا گیا کہ اب تمہاری ترقی اسلام سے وابستہ ہے (دیکھو پچھلی آیات )توان کے دلوں میں یہ سوال پیداہوسکتاتھا کہ جس چیز یعنی سبت کے قائم کرنے پر ہماری عزت کاانحصار ہے.مسلمانوںکےساتھ ملنے سے توہم اس سے اوربھی دور جاپڑتے ہیں.کیونکہ مسلمانوں میں جمعہ کی عزت کی جاتی ہے ،اورہمار ے لئے ہفتہ کے دن کی عزت کرناواجب ہے.اوراس سوال کا جواب دیناضروری تھا چنانچہ اس آیت میں اس سوال کا جواب دیا ہے اوربتایاہے کہ تباہی خداکے کلام کی نافرمانی سے آتی ہے.سبت کے توڑنے پر تباہی بھی اسی وجہ سے آئی تھی.کہ خدا نے اس کی عز ت کاحکم دیا تھا اوراب جبکہ خدا کا یہ حکم ہے.کہ اسلام کے ذریعہ جو نیاعہد قائم کیاگیاہے.اس میں داخل ہوجائو تواب تباہی اس حکم کی خلاف ورزی سے آئے گی.اس لئے اب تم سبت کی حرمت کو قائم کر کے بھی عزت حاصل نہیں کرسکتے.اب عزت صرف اسلام میں داخل ہونے اور اس کی اتباع کرنے ہی سے حاصل ہوسکتی ہے.
Page 252
اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (اوراے رسول)تو(لوگوں کو)حکمت اوراچھی نصیحت کے ذریعہ سے اپنے رب کی راہ کی طرف بلا اوراس طریق وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ١ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ سے جوسب سے اچھا ہو.ان سے (ان کے اختلافات کے متعلق )بحث کرتیرارب ان کو (بھی)جواس کی راہ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ۰۰۱۲۶ سے بھٹک گئے ہوں.(سب سے )بہترجانتا ہے.اوروہ ہدایت پانے والوں کو(بھی سب سے )بہترجانتا ہے.حلّ لُغَات.الْحِکِمْۃ:اَلْحِکْمَۃُ کے معنے ہیں.اَلْعَدْلُ.عدل.اَلْعِلْمُ.علم.اَلْحِلْمُ.بردباری.اَلنُّبُوَّۃُ.نبوت.قِیْلَ مَایَمْنَعُ مِنَ الْجَھْلِ.جوجہالت سے روکے.وَقِیْلَ کُلُّ کَلَامٍ مُوَافِقُ الْحَقِّ.ہروہ بات جو حق کے موافق ہو.وَقِیْلَ وَضْعُ الشَّیْءِ فِیْ مَوْضِعِہِ وَصَوَابُ الْاَمْرِ وَسَدَادُہُ اوربعض نے کہا ہے کہ کسی چیز کو برمحل رکھنا اور کسی معاملہ کادرست اورصحیح ہوناحکمت کہلاتاہے.(اقرب) تفسیر.چونکہ دین کی اشاعت ا ب وسیع ہونے والی تھی.اوریہود اورنصاریٰ میں جن کے پاس الٰہی کتابیں تھیں اسلام کی منادی ہونے والی تھی.اس لئے فرمایا کہ ان کے مقابلہ میں زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے.مشرکوں کے مقابلہ میں یہ آسانی تھی کہ شرک کاردّکردینے سے ہی سب جھگڑے کافیصلہ ہوجاتا تھا.مگریہود نصاریٰ کے مقابلہ میں شریعت کی تفصیلی بحثوں میں بھی پڑنالازمی تھا.اس لئے پہلے سے یہ تاکید کردی کہ دعوۃ بالحکمۃ ہو.حکمت کے مختلف معنوں کے لحاظ سے آیت کے معنی حکمت کے معنی کئی ہیں.مثلاً علم ،پختگی ، عدل، نبوت،حلم اوربردباری.جوچیز جہالت سے روکے.جوکلام حق کے موافق ہو.محل وموقع کے مناسب حال بات.یہ سب معنے یہاں چسپاں ہوتے ہیں.فرمایاحکمت کے ساتھ بلائو.یعنی علمی باتوںکوبیان کرو.یعنی پہلے نبیوں کے صحیفوں پر مسائل کی بنیاد رکھ کربات کرو.افسوس کہ مسلمان مفسروں نے اس حکم کی طرف توجہ نہیں کی.اورلوگوںسے سن سنا کر بائیبل کے متعلق ایسے حوالے اپنی کتب میں لکھ دیئے ہیں کہ یہود اورعیسائیوں کو آج تک ان کی وجہ سے اسلام پرحملہ کرنے کاموقعہ ملتا ہے.دوسرے یہ فرمایا کہ پختہ باتیں بیان کرو کوئی بات بھی کچی نہ ہو
Page 253
.بعض دفعہ انسان تائیدی دلائل کو مستقل دلائل کی صورت میں پیش کردیتا ہے.جس کا نتیجہ یہ ہوتاہے کہ دشمن انہی کو پکڑ کر بیٹھ جاتاہے.فرمایا.پہلے ہردلیل کو اچھی طرح سے جانچ لو.جو پختہ اورمضبوط ہو اسی کو پیش کرو.عدل کے لفظ سے ایک نصیحت عد ل کے معنی کے روسے یہ ہدایت فرمائی کہ کسی پر ایسااعتراض نہ کروجو تم پر بھی پڑتاہو.کیونکہ اول تویہ انصاف سے بعید ہے.دوسرے دشمن موقعہ پا کر بحث میں اس بات کو پیش کردیتاہے اورپھر شرمندگی اٹھا نی پڑتی ہے.آریہ اور عیسائی صاحبان کا اسلام کے خلاف بے انصافی سے اعتراض کرنا آج کل آریہ اورعیسائی اسلام کے خلاف اسی بے انصافی سے کام لے رہے ہیں.یعنی وہ ایسے اعتراض اسلام پر کرتے ہیں جوان کے مذہب پر زیاد ہ پڑتے ہیں.حالانکہ وہ باتیں جن پر وہ اعتراض کرتے ہیں.اگر عیب ہیں تو پھر وہ اپنے مذہب کوکیوں مانتے ہیں.اسلام ایسے اعتراضوں سے منع کرتاہے.مگرافسوس کہ اس زمانہ کے مسلمان اس نصیحت سے بالکل غافل ہیں.اوراحمدیہ جماعت کے بانی کے خلاف ایسے امو رکواعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جو سب انبیاء میں پائے جاتے ہیں.اگروہ امورقابل اعتراض ہیں توان کی وجہ سے سب ہی نبیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے.حکمت کے معنی حلم کے (۴)حکمت کے معنے حلم کے بھی ہوتے ہیں.فرمایا کہ نرمی کے ساتھ اور عقل سے کام لیتے ہوئے بات کیاکرو.کیونکہ جوشخص ایسا نہیں کرتا بلکہ جلد تیز ہوکر غصے اورجو ش میں آجاتاہے وہ دوسرے کو ہرگز سمجھا نہیںسکتا.(۵)نبوت کے معنوں کی رُو سے یہ مطلب ہوگا کہ الٰہی کلام کی مدد سے لوگوں کو دین کی طرف بلائو.جودلائل خود قرآن کریم نے دئے ہیں انہی کو پیش کرو.اپنے پاس سے ڈھکونسلے نہ پیش کیاکرو.آہ!اگر اس گُر کو مسلمان سمجھتے تویہودیت اورعیسائیت کو کھا جاتے.ہماراہتھیار قرآن کریم ہی ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاھِدْھُمْ بِہٖ (الفرقان: ۵۳)اس قرآن کی تلوار لے کر دنیاسے جہاد کے لئے نکل کھڑاہو.پرافسو س کہ آج دنیا کی ہرچیز مسلما ن کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر نہیں تویہی تلوار ،جس کو لے کر نکل کھڑے ہونے کا حکم تھا.(۶)مَایَمْنَعُ مِنَ الْجَھْلِ کی رُو سے آیت کایہ مطلب بنے گا کہ تم ایسے طریق سے کلام کیاکرو.جس کو دوسراسمجھ سکے.اوراس سے اس کی غلط فہمی دورہوسکے.یعنی وہ بات ہونی چاہیے جوجہالت کاقلع قمع کرے.اورمخاطب کے فہم کے مطابق ہو.چنانچہ حدیث میں بھی آتاہے.’’ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ وَسَلَّمَ اَنْ نُکَلِّمَ النَّاسَ عَلیٰ قَدْرِ عُقُوْلِھِمْ‘‘(فردوس الاخبار للدیلمی فصل امر امرنا)کہ ہم کو
Page 254
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں سے ان کے فہم اورادراک کے مطابق کلام کیا کرو.بعض لوگ لیکچردیتے ہیں توموٹے موٹے لفظ اوراصطلاحیں استعمال کرکے رعب ڈالنا چاہتے ہیں.ان تقریروں سے جاہلوں پر رعب توضرور پڑ جاتاہوگا.مگر فائدہ ان کی تقریر سے کوئی نہیں اٹھاتا.(۷) مُوَافِقُ الْحَقِّ کلام کوبھی حکمت کہتے ہیں.ان معنوں کے رُو سے آیت کامطلب یہ ہوگاکہ ایسی بات کیاکر و.جوسچی اورواقعات کے مطابق ہو.بعض لوگ یہ سمجھ کر کہ ہم سچے دین کی طرف ہی بلارہے ہیں.بعض غلط باتوں کو بھی بیان کردیتے ہیں.فرمایاکہ یہ طریق غلط ہے.دشمن کے مقابلہ میں جوبات کہو سچی کہو.دوسروں کو ہدایت دیتے دیتے خودہی گمراہ نہ ہوجائو.جیسے کہ فرمایا لَایَضُرُّکُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَاھْتَدَیْتُمْ(المائدۃ:۱۰۶) اگرتم ہدایت پر قائم رہتے ہو.تواس کی پرواہ نہ کرو کہ دوسراگمراہ ہوتا ہے.یعنی کوئی ایسی بات جو گناہ ہو اس خیال سے نہ کرو کہ اس کے ذریعہ سے میں دوسرے کو ہدایت دوں گا.جب تمہاری ہدایت اور دوسرے کی ہدایت ٹکراجائے توا س وقت تم اپنی ہدایت کی فکر کرو.اور دوسرے کی ہدایت کو خدا پرچھوڑدو.کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ مومن کافرہوجائے اورکافرمومن.وہ تودوسروں کو ہدایت دینا چاہتا ہے.(۸)حکمت.محل وموقع کے مناسب کلام کو بھی کہتے ہیں.ان معنوں کے روسے مطلب آیت کایہ ہوگاکہ تبلیغ میں برمحل بات کرنی چاہیے.اگربعض دلائل سے دشمن کے برانگیختہ ہونے کااندیشہ ہو ،اورخطرہ ہو کہ وہ اس طرح سے تمہار ی بات نہ سنے گا.تویہ مناسب نہیں کہ بلاوجہ اس کو چڑائو.تم اس کے سامنے دوسرے دلائل بیان کروجن کو وہ ٹھنڈے دل سے سن سکے.گویابات کرتے وقت پہلے مزاج شناسی کرلو.اگرتم ان کو خوامخواہ بھڑکائو گے ، توکوئی فائد ہ نہ ہو گا.اللہ اللہ کیامختصر الفاظ میں تبلیغ کے سب گُر بیان کردیئے ہیں.جوشخص بھی ان پر عمل کرےگاکبھی اپنے مقصد میں ناکام نہیں رہے گا.اَلْمَوْعِظَۃُ الْحَسَنَۃُ موعظہ حسنہ کے معنے پہلے گزر چکے ہیں.(یعنی وہ کلام جو دلوں کو نرم کردیتاہو،اوران پر گہرااثر ڈالتاہو ) اس نصیحت سے مسلمانوں کو ادھر توجہ دلائی کہ خشک دلیلوں ہی سے کام نہ چلایاکرو.بلکہ جذبا ت کو ابھارنے والی بات بھی کیاکرو.اورحکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کو بھی شامل رکھاکرو.حسنہ کالفظ رکھ کر بتادیا کہ جھوٹی غیرتیں نہ دلائو.جیساکہ آج کل کے جاہل علماء لوگوں کو بلاوجہ راستبازوں کے خلاف بھڑ کاتے ہیں.جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ کہنے سے مراد جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ کہہ کر یہ بتایاہے کہ ان سے جھگڑا
Page 255
کرتے وقت یہ بھی مدنظررکھاکرو.کہ مختلف دلائل میں سے جوسب سے اعلیٰ اورمضبوط دلیل ہو ،اس کو بطوربنیاد اورمرکز کے قائم کیاکرو.اورباقی دلائل کو اس کے تابع.کیونکہ تائیدی دلیل کے ٹو ٹ جانے سے اصل دلیل کوکوئی ضعف نہیں پہنچتا.برخلاف اس کے کہ اگر مرکزی نقطہ کمزورہوتومضبوط تائیدی دلائل بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ میں بتلایا ہے کہ تم اچھی طرح سے تبلیغ کرتے رہو.لیکن اگرلوگ نہ مانیں تواس سے یہ نتیجہ نکا ل کر مایوس نہ ہوجاناکہ ہمیں تبلیغ کرنی ہی نہیں آتی.کیونکہ بہت ممکن ہے کہ تمہاری تبلیغ میں کوئی نقص نہ ہو.مگرمخاطب کے دل پر اس کے گناہوں کاایسازنگ ہو کہ خدا تعالیٰ اس کے لئے ہدایت کی کھڑکی نہ کھولے.غرض تبلیغ میں منہمک رہنا چاہیے.نتیجہ نکالنا اوراثر پیداکرنا خدا تعالیٰ کاکام ہے.وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ١ؕ وَ لَىِٕنْ اگر تم(لوگ زیادتی کرنے والوں کو )سزادوتو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہو تم اتنی(ہی)سزادواور(ہمیں اپنی ذات صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ۰۰۱۲۷ کی قسم ہے کہ )اگرتم صبر کروگے توصبرکرنے والوں کے حق میں وہ (یعنی صبر کرنا)بہترہوگا.حلّ لُغَات.عاقَبْتُمْ عَاقَبْتُمْ عَاقَبَ سے جمع مخاطب کاصیغہ ہے.اورعَاقَبَ فُلَانٌ بِذَنْبِہِ (وَعَلٰی ذَنْبِہِ مُعَاقَبَۃً وَعِقَابًا)کے معنے ہیں ، اَخَذَہُ بِہِ اس کے قصورپر گرفت کی اورسزادی.پس اِنْ عَاقَبْتُمْ کے معنے ہوں گے اگرتم سزادو.(اقرب) تفسیر.بعض مفسرین نے پہلی آیات کو اس آیت سے منسوخ قراردیا ہے.لیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ منسوخ ہونے والی ان میں کونسی بات ہے.کیاعلم سے بحث کرناحکمت اورپختہ بات اورسچی بات کاکہنا اوربردباری سے کلام کرنا منسوخ ہیں یامنسوخ ہونے والی باتیں ہیں ؟پس یہ آیتیں ہرگزمنسوخ نہیں.اس آیت کامطلب صرف یہ ہے کہ تمہارے دشمن تمہاری دعو ۃ بالحکمۃ کوسن کر نہیں مانیں گے بلکہ تمہارے قتل کرنے کے لئے تلواریں اٹھائیں گے.توفرمایا کہ جب ایساہو توتم کو بھی اپنے دفاع کے لئے تلوار اٹھانے کی اجازت ہوگی.
Page 256
یہ کتنا معجزانہ کلام ہے کہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں ،یہود سے کوئی مقابلہ شروع نہیں ہوانہ نصاریٰ سے.مگر مکہ ہی میں یہ خبردےدی گئی کہ یہود بھی اورنصاریٰ بھی تم پر ظلم اورزیادتی کریں گے.اوراس وقت دفاع کے طورپرتم کو ان کے مقابلہ کی اجازت ہوگی.ہاں یہ نصیحت یاد رکھنا کہ جلد بازی نہ کرنا اورپہلے صبر کانمونہ دکھا نا پھر کوئی چارہ نہ رہے تومقابلہ کرنا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی پوری تعمیل کی اوردیر تک اہل کتاب کے ظلم سہے اورآخر مجبوراً ان کے مقابلہ پر نکلے.جہاد کا حکم دیتے ہوئے قرآن مجید کی اخلاقی خوبی قرآن کریم کی یہ کتنی بڑی اخلاقی خوبی ہے کہ جہادکاحکم دینے سے پہلے اس نے اس کی حدودوقیود کو بیان کرناشروع کردیا ہے تازیادتی کرنے کا احتمال ہی باقی نہ رہے.عقاب کے لفظ میں یہ اشارہ کیا ہے کہ ناجائزحملہ کاجوا ب ہی جہاد کہلاتاہے ،جارحانہ حملہ جہاد نہیں کہلاسکتا کیونکہ عقاب کالفظ اس فعل کے متعلق بولاجاتاہے.جودوسرے کے فعل کے جواب میں کیاجائے.پس اس لفظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب سزادو ، جرم کے بعد دو بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ کے الفاظ سے یہ ہدایت کی ہے کہ سزادینی ہی پڑے توبھی یہ خیال رہے کہ جتنی تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے.اس سے زیاد ہ نہ ہو.لَىِٕنْ صَبَرْتُمْ میں صبر کی تلقین لَئِنْ صَبَرْتُمْ میں صبر کی ترغیب دی ہے اور بتایا ہے کہ صبر اپنے نتیجہ کے لحاظ سے نہایت ہی اعلیٰ ہوتاہے.جنگ اُحد میں حضرت حمزہ(آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے چچا)اورشہداء احد کے ساتھ کفار نے یہ سلوک کیا کہ ان کے ناک اورکان بھی کاٹ دیئے (یعنی مثلہ کیا)مگرآنحضر ت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا.اورموقعہ پانے پر بھی اس قبیح اورننگِ انسانیت رسم کی اجازت نہ دی.بعض اوقات کفار معاہدات توڑتے تھے.مگر آپؐ صبر ہی فرماتے تھے (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام غزوۃ احد).صبرکانتیجہ بہترہوتاہے.بدلہ لینے سے صرف انسان کا غصہ دو رہوجاتا ہے.مگر صبر کرنے کی صورت میں اس کی روحانیت ترقی کرجاتی ہے.
Page 257
وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور(اے رسول)توصبر کر اورتیراصبر کرنا اللہ( تعالیٰ کی مدد)سے ہی(وابستہ)ہے اورتوان (لوگوں کی حالت) وَ لَاتَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ۰۰۱۲۸ پر غم نہ کھا اورجو تدبیریں و ہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے تکلیف محسوس نہ کر.حلّ لُغَات.ضَیْقٌضَیْقٌ ضَاقَ (یَضِیْقُ)کامصدر ہے اورضَاقَ الشَّیْءُ کے معنی ہیں ضِدُّاِتَّسَعَ.کوئی چیز تنگ ہوگئی.ضَاقَ الرَّجُلُ اس نے بخل سے کام لیا.نیز اَلضَّیْقُ کے معنے ہیں اَلشَّکُّ فِی الْقَلْبِ دل میں شک ہونا.مَا ضَاقَ عَنْہُ صَدْرُکَ جس سے دل تنگ پڑے اورتکلیف ہو.(اقرب)پس لَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ جوتدبیریں وہ کرتے ہیں ان سے تکلیف محسوس نہ کر.تفسیر.اس آیت میں صبر کالفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہواہے اورمضمون میں تکرار نہیں ہے.اس جگہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ جب کفارکےساتھ جنگ کی اجازت ملی توآنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے یہ سمجھ لیاکہ اب کفار پر عذاب آنے والا ہے.اس لئے آپؐ پر یہ حکم نہایت شاق گزرا اورآپؐ کادل بھر آیا.جس پراللہ تعالیٰ نے فرمایا.کہ اے رسول، اللہ کایہی فیصلہ ہے تم صبر کرو.گویا اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے ان کے صدمہ میں ہمدرد ی کا اظہار فرماتا ہے.آنحضرت ؐ کے اخلاق کا کمال اس آیت سے آپ کے اخلاق کاکمال ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو دن رات تنگ کرتے تھے اورحضورکی جان کے درپے رہتے تھے ان کی تباہی کی خبر پاکربھی آپ بے چین ہوگئے حتّٰی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.’’وَمَاصَبْرُکَ اِلَّا بِاللّٰہ‘‘کہ تجھے اتنارنج ہے کہ ہم ہی تجھےتوفیق دیں توتُو صبر کرسکے گا.ورنہ یہ غم بہت زیادہ ہے.اس جملہ کے یہ بھی معنے ہوسکتے ہیں کہ توصبر کر کیونکہ تیراصبر کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے.اورایساصبرہی اعلیٰ اخلاق میں سے ہوتا ہے.جوصبر کمزور ی اورضعف کی وجہ سے ہوتاہے وہ بے چارگی ہے اعلیٰ اخلاق میں سے نہیں.طاقت رکھتے ہوئے خاموش رہنا ہی اعلیٰ اخلاق کو ظاہرکرتاہے.وَلَاتَحْزَنْ عَلَیْھِمْ سے اوپر کے معنوں کی تائید ہوجاتی ہے.حَزِنَ عَلَیْہِ دوسرو ں کی تکلیف پرغم کرنے پربولاجاتاہے.پس ان الفاظ کی موجودگی میں اس
Page 258
آیت میں صبر کے معنے ذاتی تکلیف پر صبر کے کرنا بالکل بے جوڑ بات ہے.ان الفاظ سے ثابت ہوتاہے کہ اس آیت میں صبرسے مراد دشمن کی تباہی پرغم نہ کرناہے.لَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ کا مطلب وَ لَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ.ان الفاظ کے یہ معنی نہیں کہ ان کی شرارتوں پر غصے نہ ہو.بلکہ اس جگہ یہ الفاظ اسی کیفیت کوظاہرکرتے ہیں جوبعض دفعہ ماں کے دل میں اس وقت پیداہوتی ہے جب اس کی اولادشرارت کرکے کسی عذاب میں مبتلاہوتی ہے جس سے وہ ان کو بچانہیں سکتی.اس وقت وہ ان کو خوب کوستی ہے.یہ کوسنا غصہ کا نہیں ،غم اوررنج کاہوتاہے.اوراس کامطلب صرف یہ ہوتاہے کہ نہ تم ایسے کام کرتے اورنہ تم کو یہ دکھ پہنچتا.اورنہ تمہارے ساتھ میں دکھ پاتی.محمدؐ رسول اللہ کے ایسے ہی جذبات کی اس جگہ ترجمانی کی گئی ہے.اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَؒ۰۰۱۲۹ اوریاد رکھ کہ اللہ(تعالیٰ)یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہوں نے تقویٰ( کاطریق)اختیار کیا ہو.اورجونیکو کار ہوں تفسیر.متقی انسان وہ ہوتاہے جو خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرلے.اوراتنا بڑھا لے کہ خدا تعالیٰ خو د اس کی سپر بن جائے.اوراس کامحافظ ہوجائے اورمحسن وہ ہے جو خود حفاظت میں آجا نے کے بعد دنیا کوبھی خدا کی حفاظت میں لانے کی کوشش کرے.پس محسن کادرجہ متقی سے اعلیٰ ہے.بعض لوگ خود بہت نیک ہوتے ہیں مگر دوسروں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے.اوربعض دوسروں کی فکر توکرتے ہیں.مگر اپنی ذاتی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے.فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معیت حاصل کرنے کے لئے دونوں باتیں ضروری ہیں یعنی متقی ہو اورمحسن بھی.متقی کی تعریف اس جگہ یہ بات یادرکھنی چاہیے.کہ متقی کے یہ معنے نہیں جسے دنیا کی ہوش ہی نہ ہو.قرآن میں ایسے شخص کانام جاہل آیاہے.متقی تو وہ ہوتاہے جس کے ہرکام میں خشیت خدانظرآرہی ہو.جوکوئی کام ہی نہیں کرتا.اس میں خشیت کہاںسے پیداہوگی.متقی کاتولفظ ہی بتاتا ہے کہ وہ خطرات میں پڑتا ہے.مگرخدااس کی حفاظت کرتا ہے.پس متقی وہ ہے ،جودنیا کے کاموں میں پڑے مگر اس کے بداثر سے محفوظ رہے.محسن کے تین معنی محسن کے متعلق بھی یادرکھنا چاہیے کہ اس کے معنے مسر ف کے نہیں ہوتے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیں.کہ تواگر اپنے وارثوں کے لئے مال چھو ڑجائے تویہ اس سے بہتر ہے کہ
Page 259
توانہیں اس حالت میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں (بخاری کتاب النفقات باب فضل النفقۃ علی الاھل).محسن کے یہ معنے بھی ہیں کہ وہ ایسے کام کرنے والاہو ،جن سے دنیا میں حسن پیداہو.جس نے اپناگھر ہی اجاڑ لیا.اس نے حسن کیا پیداکرنا ہے.پس محسن وہ ہے جواپناگھر محفوظ رکھتا ہے.اورپھر دنیا کی خبر گیری کرتاہے.مگراس کے یہ معنے بھی نہیں کہ خود توعیاشیوں میں پڑا رہے لیکن جب خرچ کرنے کاموقعہ آئے توکہے کہ میرے پاس کچھ نہیں.اسی طرح محسن وہ ہے جس کے فعل کانتیجہ اچھا نکلے.پس جس کے اتفاق سے بدنتیجہ نکلے خواہ اخلاقی یاتمدنی وہ محسن نہیں ہے.اس آیت میں یہود و نصاریٰ سے جنگ کانتیجہ بھی بتادیا ہے.اوروہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کاساتھ دے گا.اورظاہر ہے.کہ جس کے ساتھ خداہو ،اس پر کون فتح پاسکتاہے.
Page 261
سُوْرَۃُ بَـنِیْٓ اِسْرَآئِیْلَ مَکِّیَّۃٌ سورۃ بنی اسرائیل ۱؎ یہ سورۃمکی ہے وَ ھِیَ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ مِائَۃٌ وَّاثْنَتَاعَشْرَۃَ اٰیَۃً وَاِثْنَا عَشَرَرُکُوْعًا اوربسم اللہ سمیت اس کی ایک سوبارہ آیا ت ہیں اوربارہ رکوع ہیں.وجہ تسمیہ ۱؎ اس سورۃ کانام بنی اسرائیل اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں وہ واقعات بیان کئے گئے ہیں جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے اورمسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں بھی یہ واقعات پیش آئیں گے کیونکہ رسول کریم صلی للہ علیہ وآلہ وسلم کومثیل موسیٰ قراردے کر مسلمانوں کو بنی اسرائیل قراردیا گیا تھا.پس اس مشابہت کی وجہ سے مسلمانوں سے بھی یہود سے ملتے جلتے واقعات کاپیش آنا ضرو ری تھا.اوراسی کی طرف اس سورۃ میں توجہ دلائی گئی ہے.اوربنی اسرائیل کی تاریخ کے دوحصوں میں سے پہلے حصہ کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لےکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے واقعات کوبیان کرکے مسلمانوںکی اس سے مشابہت بتائی گئی ہے.اس سورۃ کادوسرا نام ا سراء بھی ہے.کیونکہ اسے اسراء کے ذکر سے شرو ع کیاگیا ہے.اوراس لئے بھی کہ اسراء اس کااہم مضمون ہے.یہ سورۃ مکی ہے یہ سورۃ بعض کے نزدیک باجماع مکی ہے (بحر محیط سورۃ بنی اسرائیل )مگر بعض نے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسے آٹھ تک آیات مدنی ہیں.ابن عباس ؓ اورزبیرؓ سے ابن مردویہؒ نے روایت کی ہے کہ یہ سورت مکی ہے اورنہایت ابتداء میں ناز ل ہونے والی سورتوں میں سے ہے یعنی بعثت کے تیسرے چوتھے سال نازل ہوئی ہے.بخا ری میں ابن مسعود ؓ سے روایت ہے.’’قَالَ فِیْ بنیْٓ اِسْرَائِیْلَ وَالْکَھْفِ وَ مَرْیَمَ اِنَّھُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْاُوَلِ وَھُنَّ مِنْ تِلَادِیْ‘‘.(بخار ی کتاب تفسیر القرآن باب قولہ و منکم من یرد الی ارذل العمر ) یعنی عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں.بنی اسرائیل اورکہف اورمریم شر وع میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے بھی پہلے حصہ کی ہیںاوریہ میرے پرانے مال میں سے ہیں یعنی جن سورتوں کو میں نے شروع میں یاد کیا ہے ان میں یہ سورتیں بھی ہیں.اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری سور ۃ یا اس کاکچھ حصہ ابتدامیں نازل ہواتھا.مگر یہ واضح نہیں کہ ابتدا سے ان کی کیا مراد تھی.یعنی عبداللہ بن مسعودؓ کے ذہن میں ابتدائی سالوں کی کیاتعیین تھی.میرے نزدیک یہ سورۃ بالکل ابتدائی سالوں کی نہیں ہے بلکہ چوتھے سال سے شروع ہوکر اس کانزول دسویں
Page 262
گیار ہویں سال تک جاکر ختم ہواہے.بشرطیکہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓکے حافظہ نے غلطی نہ کی ہو.اگر ایسا ہو تویہ ساری سورۃ غالباً دسویں اور گیارہویں سال میں نازل ہوئی ہے.بلکہ ہوسکتا ہے کہ گیارہویں، بارہویں سال میں نازل ہوئی ہو.مسیحی مفسرین قرآن نے بھی اس سورۃ کا زمانہ نزول ۶ بعد نبوت سے لیکر ۱۲ بعد نبوت بتایاہے.(تفسیر القرآن از ویری جلد ۳ صفحہ ۵۲،۵۳)یہ الٰہی تصر ف ہے کہ ان لوگوں کے منہ سے یہ صداقت نکلی ورنہ ان کا فائدہ اس میں تھا کہ و ہ اسے بعد ہجرت بتاتے.اس سورۃکا پہلی سورۃ سے تعلق پہلی سورۃ سے اس سورۃ کا یہ تعلق ہےکہ پہلی سورۃ میں مسلمانوں کی ترقی کی خبر دی تھی اوربتایا تھا کہ انہیں بڑی بڑی حکومتیں ملیں گی اورساتھ ہی ہوشیا ر بھی کردیاتھا کہ یہود نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اورترقی کے ایام میں خدا کی عبادت کو بھول گئے.(اس امر کی طرف اشار ہ سبت کے لفظ سے کیا گیاتھا.دیکھو سورۃ نحل ع ۱۶)اے مسلمانو!تم نہ بھولنا.بلکہ اس زمانہ میں پہلے سے زیادہ عبادت میں مشغول ہونا.اس سور ۃ میں اس طرف بھی اشار ہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کوان ممالک کابادشاہ بنادیاجائے گا جن پریہود کی حکومت تھی.کفار کےساتھ مسلمانوں کے مقابلہ اور مسلمانوں کی فتح کی پیشگوئی اس سورۃ کی ابتداکو پہلی سور ۃ کی انتہاسے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورۃ کے آخر میں یہ پیشگوئی تھی کہ اب عنقریب تمہار امقابلہ اہل کتاب سے شروع ہوگااوروہ بھی تم کو کفار کی طرح دکھ دیں گے لیکن ان کے مقابلہ پر بھی اس وقت تک صبر سے کام لینا جب تک کہ مجبوری نہ ہو.اوریاد رکھنا کہ ان کے مقابل پر اللہ تعالیٰ تم کواسی طرح فتح دے گا جس طرح کفار مکہ پر فتح دینے کاوعدہ ہے.اب سور ۃ اسرا ء میں اس مقابلہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ مقابلہ مدینہ میں جاکرشروع ہوگا.اوریہ کہ ا س مقابلہ کانتیجہ یہ نکلے گاکہ ان کے مقدس مقامات پر مسلمانو ںکو قبضہ اورحکومت حاصل ہو جائے گی.یہودیوں کی دو تباہیوں کے ذکر سے مسلمانوں کی دو تباہیوں کی پیشگوئی اس سور ۃ میں خصوصیت کے ساتھ یہود کی دوتباہیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ دودفعہ خاص طور پر انہوں نے نافرمانی کی اوردونوں دفعہ ہی وہ خطرناک عذا ب میں گرفتا ر ہوئے.اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی ایسی تبا ہی کے دوزمانے آنے والے ہیں مگر ساتھ ہی امید بھی دلا دی کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیّٖن ہیں اس لئے آپ کاسلسلہ یہود کی طرح تباہ نہ ہوگا بلکہ ان ابتلائو ں کے بعد اوربھی شان سے چمک اٹھے گا.
Page 263
پہلی سور ۃ میں جو بعض باتیں اشارۃً فرمائی تھیں اس سورۃ میں ان کو واضح کیا گیا ہے.مثلاً پہلی سور ۃ میں شہد کے متعلق فرمایا تھا کہ ’’فِیْہِ شِفَآئٌ لِّلنَّاسِ‘‘اوراس سے اشار ہ کیاتھا کہ کلام الٰہی میں بھی شفا ہے.اس سورۃ میں اس مضمون کو بوضاحت بیان فرمایا ہے.چنانچہ فرماتا ہے وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.(آیت:۸۳) ترتیب نزول یہ سورۃ نزول میں سورۃ نحل سے پہلے ہے.مگر مضمون کی ترتیب کے لحاظ سے بعد میں رکھے جانے کے قابل ہے.اس لئے جمع قرآن کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے سورہ النحل کے بعد رکھا.میں پہلے بتاچکاہوں کہ سورتوں کے نزول کی ترتیب اورتھی لیکن جمع قرآن کے وقت اس ترتیب کو بدل دیا گیا.کیونکہ سارے قرآ ن کریم کو پڑھتے ہوئے اوربعد میں آنے والوں کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے دوسری ترتیب کی ضرور ت تھی.اوریہ امر قرآن کریم کے زبردست معجزات میں سے ہے.اس کی ہر سورۃ الگ الگ مضمون پر مشتمل ہے ا ورساتھ ہی اس کے اس کی سورتوں میں زبردست اتصال بھی پایا جاتا ہے.جب نزول قرآن کے وقت الگ الگ سورتیں نازل ہورہی تھیں اوراس وقت کی ضرور ت کومدنظررکھا جاتا تھا تب بھی پڑھنے والوں کوکوئی مشکل پیش نہ آتی تھی.کیونکہ ہرسورۃ کامضمون مکمل تھا.مگرجب بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوسری ترتیب سے مرتب کیا توپھر علاوہ اس مضمون کے جو الگ الگ سورتو ں سے نکلتاتھا ایک اَورسلسلہ مضمون پیداہوگیا جس نے قرآنی مضامین کو اورزیادہ وسعت دیدی.فَتَبٰرَکَ اللہُ اَحْسَنَ الْخَالِقِیْن.اسراء کے ذکر سے شروع کرنے میں حکمت اسراء کے ذکر سے اس کو یہ بتا نے کے لئے شروع کیاگیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کاجانشین مقرر کیا گیا ہے.اس لئے ان مقامات پر بھی آپ کو قبضہ دیاجائے گا جن کاحضرت موسیٰ ؑ اوران کے اتباع سے وعدہ کیا گیاتھا.اوریہ بتانے کے لئے کہ موسیٰ ؑ کی طرح آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑے گی اوروہ ہجرت آپ کی قوم کی ترقی کا موجب ہو گی.اس کے بعد حضرت موسیٰ ؑ کا ذکر شروع کیا کہ کس طرح موسیٰ ؑ کو بھیجا اوران کی قوم کو ان کے ذریعہ ترقی دی.کس طرح انہیں متنبّہ کیا کہ ترقی کے زمانہ میں غافل نہ ہونا مگر انہوںنے اس نصیحت سے فائدہ نہ اٹھایا اورسخت سزاپائی.پھر فرماتا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے تورات سے بھی زیادہ مؤثر بنایا ہے اس کے ذریعہ سے اس سے بھی بڑھ کر تبدیلی ہوگی مگراس کے راستہ میں بھی وہی خطرہ ہے کہ جب دولت آجائے گی توفسق وفجور بھی آجا ئے گا.دنیا کاکما ناتوبرانہیں مگر اس کے ساتھ خدا کا بھی خیا ل رکھنا چاہیے اورنیکی کو ترک نہیں کرنا چاہیے.پھر نیکی کے اصو ل بتائے ہیں.پھر فرماتا ہے کہ منکرین قرآن جب ان اصول کو سنتے ہیں توبجائے غور کرنے کے اعراض اورتکبر
Page 264
سے کام لیتے ہیںاوراپنے انجام کا خیال نہیں کرتے.اگرانجام کی طرف توجہ دلائی بھی جائے تو پروانہیں کرتے.لیکن قرآن کریم کے مخالف خواہ بیرونی ہوں یا اندرونی سخت سزاپائیں گے.چنانچہ قرب قیامت میں یعنی زمانہ مسیح موعود میں ایک سخت عذاب دنیا پر تکذیب قرآن کی وجہ سے نازل ہوگااوراس وقت پھر ایک جنگ خداکے فرشتوں اورابلیس کے درمیان ہو گی.اس جنگ میں آد م کے متبعین کو غلبہ دیا جائے گا.قرآن کریم کے ابد الآباد تک رہنے کی پیشگوئی لوگ چاہتے ہیں کہ تجھے تباہ کر دیں مگرہم نے تو تیرے لئے ایک عظیم الشان مقصد تجویز کررکھا ہے.ہم تیرے نام کو آخر زمانہ تک اوردنیا کے کناروں تک پھیلا ئیں گے اورتیری قابلیت کو دنیا پر ظاہر کیا جائے گا.ہم نے اس قرآن کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ابدالآباد تک کام آئے گا.اور روحانی خزانے اس کے ذریعہ سے آہستگی کے ساتھ دنیا پر ظاہرکئے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے.پھر آخرمیں آخر ی زمانہ کی علامت بیا ن فرمائی گئی ہے.اوراس کے شرسے بچنے کاذریعہ دعاکو بتایا ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۰۰۱ (میں )اللہ(تعالیٰ)کانام لے کر (شروع کرتا ہوں )جو بے حد کرم کرنے والا (اور)بار باررحم کرنے والا ہے.سُبْحٰنَ الَّذِيْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پاک(ذات اور پاک صفات)ہے وہ (خدا)جو رات کے وقت اپنے بندہ کو (اس)حرمت والی مسجد سے (اس ) اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا١ؕ دوروالی مسجد تک جس کے ارد گر دکو (بھی)ہم نے برکت دی ہے (اس لئے )لے گیا کہ تا ہم اسے اپنے بعض نشان اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۰۰۲ دکھلائیں یقیناًوہی(خدا)ہے جو (اپنے بندوں کی پکار کو)خوب سننے والا (اوران کی حالتوں کو )خوب دیکھنے والا ہے حلّ لُغَات.سُبْحٰنَ سُبْـحٰنَکے معنے کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۱۹.سُبحٰنَ اللہ اَیْ اُبَرِّیُٔ اللہَ مِنَ السُّوْءِ بَرَاءَ ۃً.سبحان کے معنی عیوب سے پاک سمجھنے اور پاک کرنے کے
Page 265
ہیں.(اقرب) اَسْرٰی بِہٖ اَسْرٰی بِہٖ کے معنے ہیں.اس کورات کے وقت لے گیا.مزید تشریح کے لئے دیکھو حجر آیت نمبر ۶۶.اَسْرِ سَرَی سے باب افعال کاصیغہ امر ہے اورسَرَی الرَّجُلُ کے معنی ہیں سَارَ عَامَّۃَ اللَّیْلِ رات کا اکثر حصہ چلا.اَسْرَی الرَّجُلُ اِسرَاءً مِثْلُ سَرَی.اور اَسْرٰی (باب افعال ثلاثی مزید)کے معنےسَرٰی (ثلاثی مجرّد )کے ہی ہیں.وَقِیْلَ اَسْرٰی لِاَوَّلِ اللَّیْلِ وَسَرَی لِاٰخِرِ اللَّیْلِ.اوربعض محققین لغت کہتے ہیں کہ اَسْرٰی کافعل رات کے ابتدائی حصہ میں چلنے کے متعلق استعمال ہوتاہے.اورسَرٰی کا فعل رات کے آخری حصہ میں چلنے پر.اَسْرَاہُ وَاَسْرٰی بِہِ (متعدی)کے معنی ہیں.سَیَّرَہٗ بِاللَّیْلِ اَیْ سَیَّـرَہُ لَیْلًا یعنےاسے رات کو روانہ کیا.(اقرب) اَلْعَبدُ.اَلْعُبُوْدِیَۃُ اِظْھَارُ التَّذَلُّلِ وَالْعِبَادَۃُ اَبْلَغُ مِنْھَا لِاَنَّھَا غَایَۃُ التَّذَلُّلِ.عبودیت کے معنے عاجزی کے اظہا ر کے ہیں اورلفظ عبادَۃ اس مفہوم کو اداکرنے کے لئے زیادہ بلیغ ہے کیونکہ اس کے معنے انتہائی عاجزی کرنے کے ہیں.وَلَایَسْتَحِقُّھَااِلَّا مَنْ لَہٗ غَایَۃُ الْاِفْضَالِ وَھُوَ اللہُ تَعَالٰی.اورانتہائی عاجزی اسی کے سامنے کی جاسکتی ہے جس کے انعام و اکرام بہت زیادہ ہوں اورایسی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے.وَالْعِبَادَۃُ ضَرْبَانِ عِبَادَۃٌ بِالتَّسْخِیْرِ وَعِبَادَۃٌ بِالْاِخْتِیَارِ.اورعبادت کی دواقسام ہیں (۱)کسی چیز کابلاارادہ عبادت کرنا یعنی اس کا اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی کرنا.(۲)اختیاری عبادت اوریہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے.وَالْعَبْدُ یُقَالُ عَلیٰ اَرْبَعَۃِ اَضْرُبٍ.اورعبد کالفظ چار طرح پر استعمال ہوتا ہے.(۱)عَبْدٌ بِحُکْمِ الشَّرْعِ.شریعت کے روسے غلام.جس کا بیچنا اورخریدنا جائز ہو.ان معنوں کے اعتبار سے لفظ عَبْدٌ کی جمع عبِیْدٌ ہوگی.(۲)عَبْدٌ بِالْاِیْجَادِوَذٰلِکَ لَیْسَ اِلَّالِلّٰہِ.پیداکئے جانے کے باعث عبدکالفظ استعمال کیاجاتا ہے اوراس لحاظ سے عَبْدٌ کی اضافت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی.کیونکہ صرف خالق وہی ذات ہے.(۳)عَبْدٌ بِالْعِبَادَۃِ وَالْخِدْمَۃِ.عبادت اورخدمت کے باعث عبدکالفظ استعمال ہوتاہے.اس لحا ظ سے لوگ دوحصوں میں منقسم ہو جائیں گے جو محض اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرنےوالے ہیں.یعنی عَابِدٌ ان معنوں کے لحاظ سے ا س کی جمع عِبَادٌ آتی ہے.(۴) دنیا کے غلام اوردنیا دار.(مفردات) اَلمسجدُالـحرامُ:اَلْمَسْجِدُ الْـحَرَامُ اَلْکَعْبَۃُ.مسجد حرام کعبہ کو کہتے ہیں.
Page 266
الاقصیَ.الْاَقْصٰی قَصٰی سے اسم تفضیل ہے اور قَصَی(یَقْصُوْوَقَصِیَ یَقْصٰی)اَلْمَکَانُ کے معنے ہیں بَعُدَ کوئی جگہ دور ہوگئی.اوراَقْصَی کے معنے ہیں.اَبْعَدُ.بہت دور.اس کی جمع اَقَاصِیْ آتی ہے (اقرب)پس اَلْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی کے معنے ہوں گے دور والی مسجد.تفسیر.آیت اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ کی تفسیر میں اختلاف یہ آیت ان معرکۃ الآراء آیتوں میں سے ہے جن کے متعلق مفسرین میں بہت اختلاف رہا ہے.اس آیت کے متعلق قریباً سب سابق مصنف.مفسرین اور نیزاس زمانہ کے مفسر کہتے ہیں کہ اس میں معراج کاواقعہ بیان کیا گیا ہے گومعراج کی تفاصیل میں شدید اختلا ف ہے.یہ مسئلہ بوجہ اختلاف روایات اس قدر پیچیدہ ہوگیا ہےکہ مجھے اس کے سلجھانے کے لئے اس کے کئی حصے کرنے پڑیں گے.سب سے پہلے میں اس امر کولیتا ہوں کہ اس آیت کے سواقرآن کریم میں معراج کاواقعہ ایک اورجگہ بھی بیان ہواہے اوروہ سورئہ نجم ہے.اس جگہ پراللہ تعالیٰ فرماتا ہے.معراج کا ذکر سورۃ نجم میں اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى.ذُوْ مِرَّةٍ١ؕ فَاسْتَوٰى.وَ هُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى.ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى.فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى.فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى.مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى.اَفَتُمٰرُوْنَهٗ۠ عَلٰى مَا يَرٰى.وَ لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى.عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى.عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى.اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَایَغْشٰى.مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغٰى.لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى (النجم:۵ تا ۱۹) یعنی قرآن کریم ایک وحی الٰہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی طاقتوں والا ہے محمدرسول اللہ کو یہ علم سکھا یا ہے.وہ بڑی طاقت ظاہر کرنے والا اورحکومت کرنے والا خداہے.اوراس وقت اس نے یہ کلام نازل کیا جبکہ وہ (یعنی محمد رسول اللہ صلعم)اُفُقٍ اَعلیٰ پر تھے (یعنی سب سے اعلیٰ مقام پر )محمد رسول اللہ خداکے اورقریب ہوئے اورقریب ہو کر پھر نیچے کی طرف آئے یعنی بنی نوع انسان کے قریب ہوئے.حتیٰ کہ آپ دوقوسوں کے درمیان کی وتروں کی طرح ہوگئے بلکہ اس سے بھی قریب.یعنی دومشترک وتروں کی جگہ ایک ہی وتر ہوگیا.اس موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ پر وحی نازل کی جو اس قرآن میں موجود ہے.دل نے جوکچھ دیکھا تھا اس میں اس نے غلطی نہیں کی (بلکہ فی الواقع اس نے ایسا ہی دیکھا تھا )کیا تم لوگ اس بارہ میں اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا.حالانکہ اس نے یہ بات ایک دفعہ نہیں بلکہ دودفعہ دیکھی ہے اوراس نظارہ کا مقام سدرۃُ المنتہٰی ہے.اس سدرۃ المنتہٰی کے پا س ہی جنت کا مقام ہے.اس نے اس وقت اس نظارہ کو دیکھاتھا جبکہ سدرہ کو ایک عجیب پر شوکت جلوہ نے ڈھانک لیا تھا نظر نے بھی اس
Page 267
وقت غلطی نہیں کی.نہ کوئی بات کم دیکھی اورنہ زیادہ.(بلکہ جو کچھ دیکھا ٹھیک دیکھا )اس وقت (محمد رسول اللہ صلعم نے)اس (یعنی اللہ تعالیٰ) کی بہت بڑی آیات دیکھیں.سورۃ نجم میں بیان شدہ امور معراج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یہ آیا ت معراج کے واقعہ کی طرف اشار ہ کرتی ہیں اوراس کاثبوت یہ ہے کہ ان آیات میں جن امور کا ذکر ہے وہ سب معراج سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً (۱) سدرۃ المنتہٰی تک آ پ کاجانا(۲)اس وقت سدر ۃ المنتہٰی پر کسی چیز کا نازل ہونا(۳)اس کے پاس جنت کا دیکھنا (۴)قاب قوسین کی حالت کاپیداہونا (۵)اللہ تعالیٰ کادیکھنا (۶)کلام الٰہی کاوہاں نازل ہونا.یہ سب امو ر وہ ہیں کہ جن کا ذکر معراج کی حدیثوں میں آتا ہے.چنانچہ سدرۃ المنتہٰی کامعراج میں دیکھنا حضرت ابوہریرہؓ کی روایت میں آتا ہے جسے ابن جریر.ابن ابی حاتم ابن مردویہ.البزار.ابویعلیٰ اوربیہقی چھ جامعین حدیث نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے.اس کے یہ الفاظ ہیں کہ ثُمَّ انْتَھٰی اِلَی السِّدْرَۃِ.پھر آپ معراج کی رات آسمان پر جانے اور انبیاء سے ملنے کے بعد آگے بڑھے.توسدرۃ المنتہٰی تک پہنچے.(الخصائص الکبریٰ ، باب خصوصیتہٗصفحہ ۱۷۴) اسی طرح ابن جریر.ابن المنذر.ابن ابی حاتم.ابن مردویہ.البیہقی اورابن عساکر نے ابوسعید خدریؓ سے معراج کے بارہ میں روایت کی ہے.اس میں بھی آسمان پر جانے اورنبیوں سے ملنے کے بعد سدرۃ المنتہیٰ تک جانے کا ذکر ہے.اسی طرح مسند احمد بن حنبل.بخاری.مسلم اورابن جریر میں مالک ابن صعصہ کی روایت معراج کے متعلق درج ہے.اس میں بھی لکھا ہے کہ ثُمَّ رُفِعْتُ اِلَی سِدْرَۃِ الْمُنْتَھٰی.یعنی نبیوں سے مختلف آسمانوں پر ملنے کے بعد مجھے اٹھا کر سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا.(الخصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ ۱۶۵) نیز بخاری نے انس ؓ سے روایت کی ہے اس میں بھی آسمان پرجانے اورنبیوں سے ملاقات کے بعد سدرۃ المنتہیٰ تک جانے کا ذکر ہے.(بخاری کتاب بدء الخلق باب المعراج.نیز الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۵۳) دوسراامرآیات قرآنیہ میں یہ بتایاگیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدر ۃ المنتہیٰ تک پہنچے ہیں اس وقت اسے کسی چیز نے ڈھانپا ہے.جیسے کہ الفاظ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى (النجم :۱۷)سے ظاہر ہے.اس کا ذکر بھی احادیث معراج میں آتاہے.چنانچہ حضرت ابوہریرہ ؓ کی روایت میں جس کا ذکر اوپر آچکا ہے بیان ہواہے کہ جب آپؐ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے تو فَغَشِیَہَا نُوْرُ الْخَلَّاقِ عَزَّوَجَلَّ(الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۷۴) یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کے نور نے سدرۃ کو ڈھانپ لیا.نیز مسلم نے انسؓ سے جومعراج کے متعلق روایت کی ہے اس کے یہ الفاظ
Page 268
ہیں فَلَمَّا غَشِیَہَا مِنْ اَمْرِاللہِ مَا غَشِیَ تغَیَّرَتْ فَمَا اَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللہِ یَسْتَطِیْعُ اَنْ یَنْعَتَہَا مِنْ حُسْنِہَا.یعنی جب آپ سدر ۃ المنتہیٰ تک پہنچے تواللہ تعالیٰ کے ایک خاص فضل نے سدرہ کو ڈھانپ لیااوراس میں ایسا تغیر ہواکہ کوئی شخص اس کے حسن کی تعریف نہیں کرسکتا (مسلم کتاب الایمان باب الاسراء برسول اللہ و فرض صلوٰۃ).تیسری بات آیات قرآنیہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ سدرہ کے پاس جنت بھی آپ نے دیکھی.اس کا ذکر بھی معراج کی احادیث میں آتا ہے.چنانچہ نبیوں کی ملاقات کے بعد آتاہےکہ ثُمَّ اِنِّیْ رُفِعْتُ اِلَی الجَنَّۃِ پھر مجھے جنت تک لے جا یا گیا.اورپھر اس کے بعد ہے کہ ثُمَّ اِنِّی رُفِعْتُ اِلَی سِدْرَۃِ الْمُنْتَہٰی یعنی جنت کے بعد مجھے سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایاگیا.یہ روایت ابوسعید خدریؓ کی ہے اورابن جریر نے نقل کی ہے.(ابن جریر جلد ۱۵ص ۱۱) اوران کے علاوہ اورکتب حدیث میں بھی آتی ہے.معراج میں قاب قوسین کا مقام سورئہ نجم میں چوتھی بات یہ بیان کی ہے کہ ان نظاروں کے وقت میں ایک حالت پیداہوئی.جس کانام فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى رکھا گیا ہے.معراج کی روایات میں اس کا ذکر بھی ہے چنانچہ حضر ت ابوسعید ؓ کی مذکورہ بالا روایت میں سدر ۃ المنتہیٰ کے ذکر کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ فَکَانَ بَیْنِیْ وَبَیْنَہُ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْاَدْنٰی یعنے میرے اوراس کے درمیان صرف قاب قوسین یااس سے بھی کم فرق رہ گیا.(میں اس جگہ احادیث کے الفاظ کی تشریح نہیں کرتاکہ اس کاکیامطلب ہے صرف یہ بتاتاہوں کہ حدیث معراج میں وہی حالات بیان ہوئے ہیں جو سورئہ نجم میں آئے ہیں) معراج میں رؤیت باری تعالیٰ پانچویں بات سورئہ نجم کی آیات میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس موقعہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کودیکھا.جیسا کہ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى میں اشارہ کیاگیاہے.معراج کی احادیث میں بھی یہ امر کئی روایات میں بیان ہواہے چنانچہ ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکرؓکی ابن مردویہ نے نقل کی ہے.اس میں آتا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہیٰ کا ذکر فرمارہے تھے کہ میں نے پوچھا یارسول اللہ آپ نے وہاں کیا دیکھا.اس کے جواب میں آپ نے فرمایا.میںنے وہاں کچھ دیکھا.حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں.آپ کی مراد یہ تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا (الخصائص الکبریٰ جلد اول ص ۱۷۷)حضرت ابن عباسؓ کی روایت مسلم نے نقل کی ہے اس میں اوپر والی آیت کا ذکر کرکے بیان کیا ہے کہ رَاٰہُ بِفُؤَادِہٖ مَرَّتَیْنِ رسول کریم صلعم نے اپنے دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کو دودفعہ دیکھا.(مسلم کتاب الایمان باب معنی ولقد را ہ نزلۃً اُخریٰ) شب معراج آنحضرت ؐ کا اللہ تعالیٰ سے کلام چھٹی با ت سورئہ نجم کی آیات میں یہ بیان کی گئی ہے.کہ
Page 269
سدرۃ المنتہیٰ کے قریب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم سے کلام کیا.جیساکہ فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى کے الفاظ سے ظاہر ہے معراج کی احادیث میں اس ا مر کابھی ذکر آتاہے.چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ کی حدیث جو اوپر لکھی جاچکی ہے اس میں ذکر ہے کہ جب آپ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس پہنچے تو فَکَلَّمَہُ اللہُ تعالیٰ عِنْدَ ذٰلِکَ.اللہ تعالیٰ نے سدرۃ کے پاس آپ سے کلام کیا.(خصائص جلد اول ص ۱۷۴)اسی طرح ابن ابی حاتم نے انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے.اوراس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب میں اس سدرہ کے پاس پہنچا تو قَالَ اللہُ لِیْ یَامُحَمَّدُ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیااورفرمایا کہ اے محمدؐ!(آگے لمبی بات بیان ہے ).(خصائص جلد اول ص ۱۵۵) مذکورہ بالامشابہتوں سے جوسورئہ نجم کی آیات اور واقعہ معراج میں پائی جاتی ہیں.یہ امر قطعی طور پر ثابت ہوجاتا ہے کہ سورئہ نجم میں معراج ہی کا ذکرکیاگیاہے.یہ ثابت کرنے کے بعد کہ سورئہ نجم میں جورؤیت اورکلام اورسدرۃ المنتہیٰ کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ معراج کا ہی واقعہ ہے.اب میں یہ بتاناچاہتاہوں کہ سورہ نجم بالاتفاق ۵ بعد نبوت میںیااس سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کے نزول کے ساتھ ایک ایسے عظیم الشان واقعہ کاتعلق ہے کہ اس کے نزول کے متعلق کوئی شبہ ہی نہیں ہوسکتا.اوروہ واقعہ یو ں ہے.سورۃ نجم کا تعلق ہجرت سے ۵ بعد نبوت میں رجب کے مہینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کامشور ہ دیا اورفرمایا کہ مکہ میں ظلم انتہاکوپہنچ گیا ہے اورمغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس طرف ایک ملک ہے جس میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تم وہاں چلے جائو.آپ کے حکم پر بعض لوگ مذکورہ بالا مہینہ اورمذکورہ بالا سال میں مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے.ان میں آپ کے داما د حضرت عثمانؓ اورآپ کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں.(زرقانی شرح مواہب ،الھجرۃ الاولیٰ الی الحبشۃ) تلاوت سورۃ نجم اور سجدہ کفار کی حقیقت کفار کو جب ان لوگوں کی ہجرت کا علم ہو اتوانہوں نے ان کا پیچھا کیا لیکن وہ ان کو پکڑ نہ سکے اوران کے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوکر حبشہ کو روانہ ہوگئے.اوروہاں امن سے رہنے لگے.کفار کو جب یہ خبر ملی توانہوں نے عمروبن عاص اورعبداللہ بن ربیعہ کووفدبناکر نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ ان کو لوٹادے.مگر اس نے ان کی بات نہ مانی اوریہ وفد ناکا م لوٹا.اس وفد کی واپسی کے بعد ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفارمکہ آئے اورقرآن کریم سنانے کے لئے کہا.آپ نے سورئہ نجم پڑھ کر انہیں سنائی.اس میں سجدہ آتا ہے.آپ نے اس پر سجدہ کیا اورسب کفار نے بھی ساتھ ہی سجد ہ کیا اورمشہور ہوگیا کہ مکہ کے
Page 270
سب لوگ مسلمان ہوگئے ہیں.یاکم سے کم یہ کہ اس کے عمائدین مسلمان ہوگئے ہیں.کفارنے بعد میں یہ توجیہ کی کہ اس سورۃ کو پڑھتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کی بھی تعریف کی تھی.اس لئے انہوںنے سجدہ کیا تھا.مسلمان کہتے ہیں کہ شیطا ن نے اس وقت یہ کلمات بلند آواز سے کہہ دیئے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے.(میری تحقیق یہ ہے.کہ کفارنے مسلمانوں کے واپس لانے کی کوشش میں ناکام ہوکر حبشہ میں یہ جھوٹی خبر پہنچادی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہوگئے ہیں تاکہ مسلمان خود واپس آجائیں.جب بعض مسلمان واپس آگئے تواس خوف سے کہ مکہ کے قریب پہنچ کر جب ان کو اس خبر کاجھوٹ ہونا معلوم ہوگا وہ واپس چلے جائیں گے.انہوں نے یہ تدبیر کی کہ آپ کی مجلس میں آکر قرآن سننے کی خواہش کی اورسجدہ کیا.تاکہ لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوجائے اورمسلمان واپس نہ لوٹیں.اورجب یہ فائدہ اٹھالیا توبعد میں اپنے اَتباع کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لئے یہ جھوٹ بولا کہ چونکہ رسول کریم صلعم نے مشرکانہ کلمات کہہ دیئے تھے اس لئے ہم نے سجدہ کیاتھا.بہرحال اس کی تفصیل کایہ مقام نہیں.یہ مضمون سورہ حج اورسورئہ نجم میں انشاء اللہ بیان کیاجائے گا )بہرحال پہلی ہجرت پر ابھی تین ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ بعض مسلمان مکہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر حبشہ سے واپس مکہ آگئے.اس واقعہ سے جو تما م کتب تاریخ اوراحادیث میں مذکور ہے ثابت ہے کہ سورئہ نجم شوال ۵ بعد نبوت سے یقیناً پہلے نازل ہوچکی تھی اوراس میں چونکہ معراج کاواقعہ درج ہے اس لئے معراج کا واقعہ بھی یقیناً شوال ۵ بعد نبوت سے پہلے ہوچکا تھا.زمانہ واقعہ معراج معراج کے واقعہ کی تاریخ بتانے کے بعد اب میں اس واقعہ کو لیتاہوں جس کا ذکرسورئہ بنی اسرائیل میں ہے.اورجس کے متعلق میںیہ نوٹ لکھ رہاہوں.اس واقعہ کی نسبت زرقانی شرح مواہب میں لکھا ہے کہ ۱ ۱ بعد نبوت ربیع الاول یاربیع الثانی یارجب یا شعبان میں ہو اہے.(زرقانی جلد اول زیر عنوان وقت الاسراء) مسیحی مؤرخین نے اسے بارہویں سال بعدنبوت میں تسلیم کیاہے (میورلائف آف محمدصفحہ ۱۲۱) اسراء اور معراج دو مختلف وقتوں میں ہوئے احادیث میں اس کے متعلق جو روایا ت آتی ہیں وہ بھی ا س زمانہ کی تصدیق کرتی ہیں.چنانچہ ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ قَالَ اُسْرِیَ بِالنَّبِیِّ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَیْلَۃَ سَبْعَۃِ عَشَرَ مِنْ شَھْرِ رَبِیْعِ الْاَوَّلِ قَبْلَ الْھِجْرَۃِ بسَنَۃٍ (خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ ۱۶۲) یعنی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسراء کاواقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے سترہ ربیع الاول کوپیش آیا.اسی طرح بیہقی نے ابن شہاب سے روایت کی ہے کہ مدینہ تشریف لے جانے سے ایک
Page 271
سال پہلے یہ واقعہ پیش آیاتھا.نیز بیہقی نے سعدی سے روایت کی ہے کہ ہجر ت سے کوئی چھ ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیاتھا.(دونوں روایات خصائص جلد اول کے صفحہ ۱۶۲پرمذکور ہیں)نیز ابن سعد نے حضرت ام سلمہ ؓسے روایت کی ہے کہ یہ واقعہ ایک سال ہجرت سے پہلے سترہ ربیع الاول کو پیش آیا تھا.ان سب روایا ت سے یہ امریقین کے مرتبہ تک پہنچ جاتاہے کہ اسرا ء کاواقعہ ہجرت سے چھ ماہ یاایک سال پہلے گزراہے.اس کے علاوہ اورثبوت بھی اس امر کی تائید میں ہیں کہ یہ واقعہ شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعدکاہے.اورشعب ابی طالب میں آپ اورآپ کے ساتھی ساتویں سال بعد نبوت میںداخل ہوئے تھے اوردسویں سال میں وہاںسے نکلے تھے(الطبقات الکبریٰ لابن سعد ذکر حصر قریش رسول اللہ و بنی ہاشم فی الشعب).اوروہ ثبوت یہ ہے کہ حدیث اسراء کے متعلق ایک ہی موقعہ کاگواہ ہے.اوروہ امّ ہانی ؓ آپ کی چچازاد بہن ہیں جو ابوطالب کی بیٹی تھیں.وہ بیان کرتی ہیں کہ جس رات یہ واقعہ ہواہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتھے (خصائص الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۱۷۱).اوربہت سے صحابہؓ نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ آپؐ اس رات امّ ہانی کے مکان پر تھے.اورظاہر ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی یاابوطالب کی زندگی میں آ پ امّ ہانی کے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے.پس امّ ہانی کے گھرمیں آپ کاان ایام میں رہنا بھی بتاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت خدیجہ اورابوطالب کی وفات کے بعد کا ہے.اوران دونوں کی وفات بھی ۱۰ بعد نبوت میں ہوئی ہے (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام وفاۃ ابی طالب و خدیجۃ).پس اس شہادت سے بھی یہی استنباط ہوتاہے کہ یہ واقعہ گیارہویں ، بارہویں سال بعدنبوت کا ہے.واقعہ معراج نبوت کے پانچواں سال کا ہے اور اسراء گیارہویں کا خلاصہ یہ کہ تاریخ.احادیث اورعقلی استدلال سب اس ا مر کی تائید میں ہیں کہ اسرا ء کاواقعہ گیارہویں بارہویں سال بعد نبوت کا ہے.اورپہلے میں یہ ثابت کرچکا ہوں کہ معراج کاواقعہ پانچویں سال بعد نبو ت سے پہلے کاہے.پس جب ان دونوں واقعات کی تاریخوںمیں چھ سات سال کا فرق ہے توانہیں ایک واقعہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہوسکتا.اورحق یہی ہے کہ معراج کاواقعہ اَورہے اوربیت المقدس کی طرف جانے کاواقعہ بالکل اَورہے.معراج اور اسراء کے الگ الگ وقت میں ہونے کا ایک ثبوت علاوہ تاریخی شواہد کے ایک اَورامر بھی میرے اس استدلا ل کی تائید میں ہے اوروہ یہ ہے کہ حدیث معراج سے ثابت ہے کہ پانچ نمازوں کی فرضیت
Page 272
معراج کے واقعہ میں ہوئی ہے.اب اگران دونوں واقعات کو ایک سمجھا جائے توماننا پڑے گاکہ پانچوں نمازیں گیارہویں ، بارہویں سال بعد نبوت میں فرض ہوئی ہیں جوبالبداہت غلط ہے.پانچوں نمازوں کے فرض ہونے کا زمانہ شروع زمانہ نبوی سے ثابت ہے اورسب مسلمانوں کااس پر اتفاق ہے (بخاری کتاب الصلٰوۃ باب کیف فرضت الصلٰوۃ فی الاسراء).پس اس امر سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ معراج نبوی نبوت کے ابتدائی ایام میں ہواہے جبکہ اسراء کاواقعہ گیارہویں بارہویں سال میں ہواہے.بلکہ میں تویہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں جودومعراجو ں کا ثبوت ملتاہے.اس کا ذکر اس امر کے بتانے کے لئے کیاگیا ہے کہ سورئہ نجم میں جس معراج کا ذکر ہے وہ دوسرامعراج ہے.ورنہ ایک معراج نبوت کے ملتے وقت یا اس کے ساتھ ہی ہواتھا اورنمازیں اس میں فرض ہوگئی تھیں.چنانچہ بخاری نے انس ؓ سے روایت کیا ہے اورابن جریر نے بھی اپنی تفسیر میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جَاءَہٗ ثَلَاثَۃُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ یُوْحٰی اِلَیْہِِ.الخ.کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین فرشتے آئے.(بخاری کتاب التوحید باب قولہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیمًا) اوریہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے.آگے وہی معراج کاواقعہ مذکور ہے.اوراس میں بیت المقدس کی طرف جانے کا ذکر نہیں بلکہ سیدھا آسمان پرجانے کا ذکر ہے.اورآخر میں نمازوں کے فرض ہونے کا ذکر ہے.اس حدیث سے معلو م ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ کم سے کم ایک دفعہ نبوت کے ملنے سے عین پہلے یاعین اس وقت ہواہے اوریہی بات درست ہے.کیونکہ نمازیں فرض شروع اسلام سے ہیں اورایک سال بھی نبوت کے بعدایسا نہیں گزرا.جس میں نمازیں فرض نہ ہوں(اکثر محققین اس طرف گئے ہیں کہ نبوت سے پہلے کانہیں.اس وقت کاہے.راوی کوزمانہ کے قرب کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے اور میرے نزدیک بھی یہی صحیح ہے.کیونکہ نبوت سے پہلے نمازوں کا فرض ہوناعقل کے خلاف ہے ).معراج اور اسراء دو الگ الگ واقعات ہیں خلاصہ یہ کہ معرا ج اوراسراء دوالگ الگ واقعات ہیں.اور جیسا کہ سورئہ نجم کی آیات سے ظاہر ہے معرا ج دوہیں.اوراحادیث سے معلو م ہوتا ہے کہ ایک معراج نبوت کے ابتدائی ایام میں ہواہے.بلکہ کہہ سکتے ہیں اسی معراج میں شرعی نبوت کی بنیاد پڑی ہے.اورنماز یں فرض کی گئی ہیں.اوردوسرامعراج ۵ بعد نبوت میں ہواہے.یایہ کہ وہ بھی اس سے پہلے ہوچکا تھا صرف اس کا ذکر سورئہ نجم میں کیاگیا ہے.اوراسراء کاواقعہ بالکل جداہے.اورگیارہویں بارہویں سال بعد نبوت ظہور میں آیا ہے جبکہ حضرت خدیجہؓ فوت ہوچکی تھیں اور آپ امّ ہانی کے مکان میں رہتے تھے جیسا کہ متواتراحادیث اور روایات تاریخیہ
Page 273
سے ثابت ہے.واقعاتی شواہد کہ معراج اور اسراء الگ الگ واقعات ہیں تاریخی شہادت کے درج کرنے کے بعد اب میں واقعاتی شواہدسےثابت کرتا ہوں کہ یہ دونو واقعات الگ الگ ہیں.(۱)پہلی گواہی ا س بارہ میں خود قرآن کریم کی ہے.قرآن کریم میں سورئہ نجم میں معراج کے واقعہ کو بیان کیاگیا ہے اوراس میں کوئی ذکر بیت المقدس کی طر ف جانے کانہیں.اس کے مقابل پر سورئہ اسرائیل میں بیت المقدس تک جانے کا ذکر ہے.اورآسمان پر جانے کاکوئی اشارہ تک نہیں.اس سے صاف معلوم ہوتاہے کہ دونو واقعات الگ الگ ہیں.اس لئے ان کے اکٹھابیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی.ورنہ یہ نہایت قابل تعجب امر ہے کہ ایک ہی واقعہ کا آخری حصہ توچھ سال پہلے قرآن کریم میں بیان کیاگیا.اوراس کا پہلاحصہ چھ سال بعد بیان کیا گیا.شب اسراء آنحضرت ؐ امّ ہانی کے گھر تھے (۲)دوسراگواہ واقعات میں سے ان دونوں امورکے الگ الگ ہونے کا یہ ہے کہ اس واقعہ کاموقعہ کاگواہ صرف ایک ہے اوروہ امّ ہانی ہیں.آپ اس رات جب یہ واقعہ پیش آیا ہے امّ ہانی کے ہاں ہی سوئے تھے.وہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء الی بیت المقدس کا واقعہ سنایاتھا اورصبح کے وقت دوسرے لوگوں سے ذکرکرنے سے پہلے سنایاتھا.اورمیں نے اس خیا ل سے کہ لوگ اس واقعہ کے عجیب ہونے کے سبب ا س کاانکار کریں گے اورمخالفت میں ترقی کرجائیں گے آپ کو لوگوں کے سامنے اس کے بیان کرنے سے باز رکھنے کی بھی کوشش کی تھی مگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی (خصائص الکبریٰ جلد ۱ ).یہ گواہ جو موقعہ کاگواہ ہے اورجس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس سے کم سے کم سات محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس واقعہ کے متعلق روایت کی ہے.اورچار مختلف راویوں کے ذریعہ روایت نقل کی ہے.مگران چاروں روایتوں میں صرف اتنابیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس تک جاکر راتوں رات واپس آگیاہوں.اگرآپ آسمان پر جانے کا ذکر بھی اس وقت فرماتے تو ام ہانی جو سب سے پہلی گواہ ہیں.وہ کسی نہ کسی موقعہ پر توبیت المقدس سے آسمان پر جانے کا ذکر کرتیں.مگر وہ جب ذکرکرتی ہیں اورجس کے پاس ذکر کرتی ہیں یہی کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس تک جاکر واپس آیا ہوں.اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ بیت المقدس تک جانے کاواقعہ اَورہے اور معراج الی السماء کاواقعہ اورہے.
Page 274
(۳)تیسری شہادت واقعات سے یہ ہے کہ وہ راوی جنہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے ان میں سے بعض تو وہ ہیں کہ جنہوںنے سیدھاآسمان پر جانے کا ذکر کیا ہے.بیت المقدس تک جانے کا ذکرنہیں کیا.اوربعض وہ ہیں.کہ جنہوں نے بیت المقدس تک جاکر پھر آسمان پر جانے کا ذکرکیا ہے.بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس تک جانے کا ذکر کیا ہے آگے آسمان تک جانے کاکوئی ذکر نہیں کیا.لیکن ایک خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوںنے صاف کہا ہے کہ آپ بیت المقدس سے فارغ ہو کر مکہ واپس تشریف لے آئے.یہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے سیدھا آسمان پر جانے کا ذکرکیا ہے ان کی شہادت بھی یہی ہے کہ معراج کاواقعہ ایک الگ واقعہ ہے.کیونکہ اگر آپ گھر سے سیدھے آسمان کی طرف لے جائے گئے تھے توبیت المقد س راستہ میں پڑہی نہیں سکتا.یہ راوی انس.مالک بن صعصہ اورابوذر ہیں.ابوذران صحابہ میں سے ہیں جوابتدائی ایام میں اسلام لائے تھے اوراس واقعہ کے شرو ع کے سننے والوں میں سے تھے.شب اسراء میں آنحضرت ؐ صرف بیت المقدس تک گئے اسی طرح جنہوں نے بیت المقدس تک ہی جانے کا ذکر کیا ہے آگے آسمان پر جانے کا ذکر نہیں کیا.ان کی شہادت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف جب اسراء ہواہے اس وقت آنحضرت صلعم آسمان پر تشریف نہیں لے گئے ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اسراء کاواقعہ تووہ لوگ بیان کرتے لیکن اس کے اہم ترین جزو کو یعنے آسمان پر جانے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور اس کا دیدار کرنےکے حصہ کو چھوڑ دیتے.اس قسم کی روایت کر نے والے انس ؓ اورعبداللہ بن مسعودؓ ہیں اور عبداللہ بن مسعودؓ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جو شروع میں اسلام لائے اورہروقت آپ کے ساتھ رہے.وہ روایات جن سے ثابت ہے کہ آپ ؐ صرف بیت المقدس گئے تیسری قسم کی روایتیں جن سے صاف معلو م ہوتا ہے کہ آپ صرف بیت المقدس تک گئے اورپھر واپس تشریف لے آئے.وہ توظاہرہی ہے کہ اس امر کی بیّن دلیل ہیں کہ بیت المقدس کے اسراء کے ساتھ آسمان کامعراج نہیں ہوا.بلکہ ا س با رآپ صرف بیت المقدس تک لے جائے گئے تھے.ان احادیث کے راوی عبداللہ بن مسعودؓ.ابن عباس ؓ.شداد بن اوسؓ.امّ ہانیؓ.حضرت عائشہؓ اور حضرت امّ سلمہؓ ہیں.ان میں سے عبداللہ بن مسعود کا ذکر میں نے اوپر کردیا ہے.عبداللہ بن عباسؓ.حضرت عباس کے لڑکے ہیں جوآنحضرت صلعم کے چچا تھے.اوربوجہ اس کے کہ یہ واقعہ گھر میں پیش آیا تھا ان کو اس کے صحیح حالات جاننے کاسب سے بہتر موقعہ تھا.حضرت عائشہ ؓ اورامّ سلمہ ؓ آنحضرت صلعم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں اوراس واقعہ کی بہترین شاہد ہوسکتی ہیں.پھرامّ ہانیؓ ہیں جن کے گھرمیں یہ واقعہ
Page 275
گذرا.اورجن کے سامنے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ذکرکیا (بخاری کتاب الصلوٰۃ ، مسلم کتاب الایمان باب اسراء برسول اللہ،الخصائص الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۱۵۴ تا ۱۵۹ و ۱۷۶ تا ۱۷۹، العصابۃ باب الکنی حرف الذال والعین).اس بار ہ میں سب راویو ںکی روایات درج کر نا تومشکل ہے.بعض روایات بیان کر دیتا ہوں.حضرت امّ ہانیؓ کہتی ہیں کہ اسرا ء کی صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا.امّ ہانی میں نے عشاء کی نما زتم لوگوں کے ساتھ پڑھی.پھر میں بیت المقدس گیا اوروہاں نماز پڑہی.اورپھر اب تم لوگوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ رہاہوں(الخصائص الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۱۷۷).حضرت عائشہ ؓ کی روایت یہ ہے کہ جب اسراء کاواقعہ ہو ا.لوگ دوڑے دوڑے حضر ت ابو بکرؓ کے پا س آئے اوران سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کادوست کیاکہتا ہے.انہوں نے کہا کیاکہتا ہے.انہوں نے جواب دیا کہ وہ کہتاہے کہ میں رات بیت المقدس تک ہوکر آیا ہوں اگر معراج کا ذکر ساتھ ہی آپؐ نے کیا ہوتا توکفار اس حصہ پر زیادہ شور کرتے.مگرانہوں نے صرف یہ کہا کہ آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیت المقدس تک گیاتھا.پھر جب حضرت ابوبکرؓنے آنحضرت صلعم کی تصدیق کی.تولوگوں نے کہا.کیا آپ اس خلاف عقل بات کو بھی مان لیں گے.توحضرت ابوبکرؓ نے کہا میں تواس کی یہ بات بھی مان لیتاہوں کہ صبح و شام اس پر آسمان سے کلام اترتا ہے (الخصائص الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۱۷۶).اس جواب سے بھی صاف ظاہر ہے کہ اس واقعہ کے ساتھ آسمان پر جانے کاکوئی ذکر نہ تھا.ورنہ آسمان پر خود آنے جانے سے کلام کاآناجانا کسی صورت میں بھی زیادہ عجیب نہیں کہلاسکتا.اوراس صورت میں حضرت ابوبکرؓکبھی بھی وہ دلیل نہ دے سکتے تھے جو انہوں نے دی.اورنہ اس جواب کو سن کر معترض چاموش ہوسکتے تھے.وہ ضرور جواب دیتے کہ تمہارے آقاتوخود آسمان پر جانے کادعویٰ کررہے ہیں اور تم آسمان سے الہام آنے کا اس خبرسے مقابلہ کررہے ہو.مگرانہوں نے بھی آگے سے ایسا نہیں کہا.جس سے معلوم ہوتاہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیت المقد س تک جانے کا ذکرکیاتھا.آسمان پرجانے کا اس واقعہ کےساتھ کوئی ذکر نہیں کیا تھا.عبداللہ بن مسعو دؓ کی روایت میں بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھانے کے ذکرکے بعد یہ الفاظ ہیں ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَاَقْبَلْنَا.پھر ہم وہاں سے آگئے اورمکہ کی طرف چل پڑے.(خصائص ص ۱۶۲ جلد اول) چوتھاشاہد واقعا ت سے اس امر کاکہ واقعہ اسراء الگ واقعہ ہے یہ ہے کہ بعض روایتوں میں جن میں بیت المقدس جانے کے بعد آسمان پر جانے کا ذکر کیا گیاہے وہاں سے واپسی کے وقت بھی بیت المقدس میں اترنے
Page 276
کا ذکر آتاہے اوروہاں سے پھر مکہ واپس آنے کا ذکر ہے.(اَخْرَجَہٗ ابْنُ اَبِی حَاتَمٍ عَنْ اَنَسٍ منقول ازخصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ ۱۵۴) آسمان سے واپسی پر بیت المقدس سے ہوکر آناخلاف عقل ہے اب ہر عقلمند سمجھ سکتاہے کہ بیت المقدس ہوتے ہوئے آسمان پرجاناتوعقل میں آبھی سکتا تھا.کیونکہ اس میں یہ مفید غرض تھی کہ آپ اس مقام پر نماز پڑھ لیں جہاںنبیوں کی ایک بڑی جماعت نے خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایاتھا.مگرجب آپ اس سے فارغ ہوگئے اورآسمان پرتشریف لے گئے توپھر وہاں سے واپسی کیوں بیت المقدس کوہوئی اورکیوں بیت المقدس لاکر آپ کو واپس مکہ پہنچایاگیا.اگرواپسی کے وقت بھی کوئی ایساکام بتایاجاتا جو آپ نے بیت المقدس میں کیا تب تو بات سمجھ میں آسکتی تھی کہ وہ کام رہ گیا تھا.اس لئے آپ کو پھر بیت المقد س لایا گیا.لیکن کسی ایک روایت میں بھی آسمان سے واپسی پر بیت المقدس میں آپ کے کسی کام کے کرنے کا ذکر موجود نہیں.پھر اس تکلیف دہی کی غرض کیاتھی.اگرتویہ تسلیم کیا جائے کہ آسمان کوراستہ ہی بیت المقدس سے جاتا ہے اوروہاں کوئی سیڑھی لگی ہوئی ہے تب تو یہ سمجھ میں آسکتاتھاکہ مجبوراً آپ کو وہاں اتارنا پڑا.لیکن اگریہ بات نہیں ہے اورہر مسلما ن کاعقیدہ یہی ہے کہ ایسانہیں ہے کیونکہ آسمان کی طرف صعود سیڑھیوں کا محتاج نہیں ہے توپھر واپسی کے وقت بغیرکام کے بیت المقدس میں آپ کو اتار نا اورپھر مکہ کی طرف لا نا بالکل خلاف عقل ہے.میرے نزدیک اس کی ایک ہی تاویل ہوسکتی ہے کہ حضرت انس ؓ نے معراج کا اوراسراء الیٰ بیت المقدس کاواقعہ سنایا ہے راویوں میں سے کسی راوی کے ذہن میں دونوں مضمونوں کا خلط ہوکر ایک واقعہ بن گیا.ادھر اسے اچھی طرح یا دتھاکہ اسراء کی روایت میں حضرتؐ نے بیت المقدس جانے کابھی اوروہاںسے آنے کابھی ذکرکیا تھا.اس وجہ سے اس نے مجبوراً یہ سمجھا کہ معراج میں آسمان سے واپسی کے وقت آپ بیت المقدس ہی میں اترے تھے اوروہاں سے پھر مکہ تشریف لے گئے تھے.اسراء اور معراج کے واقعات میں خلط اورا س کی وجہ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر خلط ہواکیونکر ؟اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں خواہ آسمان پر جانے کا ذکر ہو یا زمین پر سفرکرنے کا اگر رات کو کوئی سفر ہوتو اسے اسراء کہیں گے(اقرب).اس وجہ سے معراج کے متعلق بھی اسراء کالفظ بولاجاتاتھا اوربیت المقد س کی طرف جانے کے واقعہ کے متعلق بھی اسراء کالفظ استعمال کیاجاتا تھا کیونکہ یہ دونوں واقعات رات کے وقت ہوئے تھے.اب ادہر دونوں کے لئے اسراء کالفظ بولاجاتا تھااورادہر ان دونوں نظاروں کی کئی باتیں آپس میں ملتی جلتی تھیں.مثلاً یہی کہ اس میں بھی براق کا ذکر آتا ہے اوراس میں بھی.اسرا ء بیت المقدس میں بھی انبیاء سے ملنے
Page 277
کا ذکرآتاہے اورمعراج میں بھی.اسراء بیت المقدس میں بھی نماز پڑہانے کا ذکر آتا ہے اورمعراج میں بھی.اسراء کی بعض روایتو ں میں بھی دوزخ جنت کے بعض نظارے دیکھنے کا ذکر آتاہے اورمعراج کے واقعہ میں بھی.غرض نام اورکام کی تفصیلات میں ایک حد تک اشتراک پایاجاتاتھا اور روحانی عالم کے عجیب وغریب نظاروں کا ذکر تھا.اس لئے بعض راویوںکے ذہنوں میں خلط ہوگیا اورانہوں نے دونوں واقعات کوایک ہی سمجھ کر ملاکربیان کرناشروع کردیا.لیکن جن کاحافظہ زیادہ مضبوط تھا انہوںنے اگرمعراج کاواقعہ صحابی سے سناتھا توروایت شرو ع ہی اس طر ح کی کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھاکر آسمان کی طرف لے جایاگیا.اوراگرانہوں نے صحابی سے اسراء بیت المقدس کاواقعہ سناتھا توانہوں نے بیت المقدس تک کاواقعہ بیان کیا.آگے آسمان پر جانے کا ذکرنہیں کیا.معراج اور اسراء دونوں کو صحابہ اسراء کے نام سے پکارتے تھے اس کاثبوت کہ دونوں واقعات کوصحابہ میں اسراء کے نام سے پکاراجاتاتھا.احادیث سے مل جاتا ہے.مسند احمد بن حنبل.بخاری.مسلم اورابن جریر میں مالک بن صعصہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا.اَنَّ نَبِیَ اللہِ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ حَدَّثَھُمْ عَنْ لَیْلَۃٍ اُسْرِیَ بِہٖ.قَالَ بَیْنَـمَااَنَا فِی الْحَطِیْمِ وَرُبَّـمَا قَالَ قَتَادَۃُ فِی الْحِجْرِ مُضْطَجِعٌ اِذَااَ تَانِی آتٍ فَجَعَلَ یَقُوْلُ لِصَاحِبِہِ الْاَوْسَطِ بَیْنَ الثَّلَاثَۃِ فَاَتَانِی فَشَقَّ مَابَیْنَ ھٰذِہٖ اِلٰی وَھٰذِہٖ یَعْنِیْ مِنْ ثُغْرَۃِ نَحْرِہٖ اِلَی شِعْرَتِہٖ فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِیْ فَاُتِیْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَھَبٍ مَمْلُوْءَ ۃٍ اِیْمَانًا وَحِکْمَۃً فَغُسِلَ قَلْبِی ثُمَّ حُشِیَ ثُمّ اُعِیْدَ ثُمَّ اُتِیْتُ بِدَآبَّۃٍ دُوْنَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ یَقعُ خَطْوُہٗ عِنْدَ اَقْصٰی طَرْفِہٖ فَـحُمِلْتُ عَلَیْہِ فَانْطَلَقَ بِیْ جِبْرِیْلُ حَتّٰی اَتَی بِیَ السَّمَآءِ الدُّنْیَا.الخ.(مسند احمد بن حنبل مسند الشامیین حدیث مالک بن صعصعۃ ) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء کاواقعہ ایک دفعہ ہمیں سنایا.آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں حطیم میں سورہاتھا (خانہ کعبہ کاوہ حصہ جوعمارت سے باہرچھوڑاہواہے.مگر طواف کے وقت اسے بھی طواف میں شامل رکھا جاتاہے)قتادہ جو تیسرے راوی ہیں ان سے اگلاراوی کہتا ہے کہ اب مجھے یہ یاد نہیں کہ قتاد ہ نے حطیم کالفظ بولاتھا یا حجر کا(یہ بھی اسی کانام ہے)خیرتورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں دوآدمیوں کے ساتھ سورہاتھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اوراپنے ایک ساتھی سے کہنے لگا کہ ان تین سونے والوں میں سے جودرمیان میں سورہاہے وہ ہے.اس پر وہ آگے بڑھا اور میرے اس حصہء بدن سے اس حصہ بدن تک اس نے ایک شگا ف دیا.آپ نے اس کے ساتھ جگہ بتانے کے لئے دونوں ہنسلیوں کے درمیان کی نرم جگہ سے لے کر ناف کے نیچے تک
Page 278
ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس حد تک انہوں نے شگاف دیا.پھر فرمایا کہ شگاف دے کر اس نے میرے دل کو باہر نکا لا.پھر ایک سونے کی سینی لائی گئی جس میں ایمان اورحکمت بھرے ہوئے تھے.پھر اس شخص نے پہلے میرادل دھویا پھر میرے اندر وہ نور بھردیاگیا.پھر ہرچیز اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی گئی.پھر ایک چوپایہ لایاگیا جوگدھے سے اونچا اورخچر سے چھوٹاتھا.اس کے قد م اس کی حد نظرتک جاکر پڑتے تھے.مجھے اس جانور پر سوار کردیاگیا اورجبرائیل مجھے لے کر چلے.یہاں تک کہ ہم پہلے آسمان پر پہنچ گئے.اسی قسم کی روایت بخاری اورابن جریر میں بھی انسؓ سے بیان کی گئی ہے.اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اسراء کی رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے سیدھے آسمان کی طرف لے جائے گئے.(خصائص جلد اول ص ۱۵۳) اس روایت میں صرف یہ الفا ظ استعمال ہوئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اسراء ہم سے بیان کیا.لیکن آگے بیت المقدس کاکوئی ذکر نہیں بلکہ سیدھا آسمان تک جانے کا ذکر ہے اورساری حدیث میں معراجِ آسمانی ہی کا ذکر ہے جس سے معلو م ہوتاہے کہ صحابہ کبھی اسراء کالفظ بولتے تھے اوران کی مراد صرف معراج ہوتی تھی اس کے برخلاف اس کابھی ثبوت ملتا ہے کہ اسراء کالفظ وہ صرف بیت المقدس کی طرف جانے کے لئے بولتے تھے.چنانچہ حدیثِ جابرؓمیں جوبخاری اورمسلم میں مروی ہے اسراء کالفظ صرف بیت المقدس تک جانے کے لئے استعمال ہواہے.(خصائص جلد او ل ص ۱۵۷) اسی طرح شدا د بن اوس کی روایت میں جوطبرانی.بیہقی اور کئی کتب حدیث نے بیان کی ہے یہ لفظ صرف بیت المقدس تک جانے اوروہاں سے مکہ واپس آنے کے متعلق بولاگیا ہے.(خصائص جلد او ل ص ۱۵۸و۱۵۹) ان دونوں قسم کی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ میں اسراء کالفظ دونوں واقعات کی نسبت مستعمل تھا.پس اس لفظ کے استعمال اوربعض تفصیلات کے اشتراک کی وجہ سے بعض راویوں کو یہ دھوکا آسانی سے لگ سکتا تھا کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی ہیں اوراس کی وجہ سے انہوں نے دونوں قسم کی روایا ت کوملاکربیان کردیا اوراس سے بعد میں آنے والے لوگوں کو یہ دھوکالگ گیا کہ شاید یہ ایک ہی واقعہ کی تفاصیل ہیں.روایات میں خلط علاوہ ازیں روایات پر تنقیدی نگاہ ڈالنے سے بھی یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ ان میں خلط ہوگیا ہے.کیونکہ جن روایات میں پہلے بیت المقدس جانے اوروہاںسے آسمان پر جانے کا ذکر ہے انہی میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ بیت المقدس میں آپ کو دوسرے انبیاء سے ملایا گیا ان میں آدم بھی تھے اور حضرت موسیٰ بھی اور حضرت عیسیٰ بھی اور حضرت ابراہیم بھی.لیکن آسمان پرجانے کے بعد پھر بیان ہواہے کہ مختلف آسمانو ں پر آپ
Page 279
نے انہی انبیاء کو دیکھا اورپہچانانہیں.اگرایک ہی وقت میں یہ دونوں واقعات ہوئے تھے تواول توآسمان پر یہ انبیاء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس طرح پہنچے.اور دوسرے ان کو تھوڑی دیر پہلے دیکھنے کے بعد آپ نے کیوںنہ پہچانا.دو مختلف وقتوں کی رؤیتوں میں تویہ امر سمجھ میں آسکتاہے کہ ایک نظارہ دوسرے سے مختلف ہو.لیکن ایک ہی وقت میں دونوں نظاروں کی صورت میں یہ بات بعید از قیاس ہے.پس یہ اندرونی شہادت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ دوالگ الگ واقعات کے بارہ میں راویوں کے ذہن میں خلط ہوگیا ہے.میرے اس خیال کی تائید بعض پرانے علماء کی آراء سے بھی ہوتی ہے.چنانچہ خصائص الکبریٰ جلد اول کے ص ۱۸۰پرلکھا ہے کہ ابونصر قشیری ابن العربی اوراَوربہت سے علماء کاخیال ہے کہ اسرا ء دودفعہ ہواہے.اس کی وجہ سے احادیث میں اختلاف ہوگیا.اس وقت تک میں یہ ثابت کرچکاہوں کہ تاریخی شہادت سے جس سے دونوں واقعات مختلف زمانوںکے ثابت ہوتے ہیں.اورقرآ ن کریم کی شہادت سے کہ اس میں معراج کاواقعہ الگ اور خالی بیت المقدس تک جانے کاواقعہ الگ بیان کیاگیاہے.اوراحادیث کی اندرونی شہادتو ں سے یہ امر ثابت ہے کہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں.اورنام اورتفاصیل کے اشتراک کی وجہ سے دھوکاکھاکر بعض راویان حدیث نے ان کو ایک واقعہ سمجھ لیا ہے اب میں اس اسراء کاکسی قدر تفصیل سے ذکرکرتاہوں جس کا اس سورۃ میں ذکر کیا گیا ہے.واقعہ اسراء کی تفصیل میرے نزدیک اسرا ء بیت المقدس کاواقعہ اپنی تفاصیل کے ساتھ حدیث انس ؓ میں جو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے نہایت صحیح طور پر بیان ہواہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں.عَنْ اَنَسٍ ابْنِ مَالِکٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبُرَاقِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّهَا ضَرَبَتْ بِذَنَبِهَا، فَقَالَ لَهَا جِبْرَائِيْلُ مَهْ يَا بُرَاقُ، فَوَاللهِ إِنْ رَكِبَكَ مِثْلُهُ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزٍ نَاءَ عَنِ الطَّرِيْقِ أَيْ عَلٰى جَنْبِ الطَّرِيْقِ فَقَالَ:مَا هٰذِهِ يَا جَبْرَائِيلُ؟ قَالَ سِرْ يَا مُحَمَّدُ، فَسَارَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيْرَ، فَإِذَا شَيْءٌ يَدْعُوْهُ مُتَنَحِّيًا عَنِ الطَّرِيْقِ يَقُوْلُ هَلُمَّ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ جِبْرَائِيْلُ سِرْ يَا مُحَمَّدُ، فَسَارَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسِيْرَ، قَالَ ثُمَّ لَقِيَهُ خَلْقٌ مِنَ الْخَلَائِقِ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آخِرُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ، فَقَالَ لَهُ جِبْرَائِيْلُ ارْدُدِ السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ لَقِيَهُ الثَّانِيْ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَةِ الْأَوَّلَيْنَ حَتَّى انْتَهٰى إِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْخَمْرُ فَتَنَاوَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرَائِيْلُ أَصَبْتَ يَا مُحَمَّدُ الْفِطْرَةَ، وَلَوْ شَرِبْتَ الْمَاءَ لَغَرِقْتَ وَغَرِقَتْ
Page 280
أُمَّتُكَ، وَلَوْ شَرِبْتَ الْخَمْرَ لَغَوَيْتَ وَغَوَتْ أُمَّتُكَ.ثُمَّ بُعِثَ لَهُ آدَمُ فَمَنْ دُوْنَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَّهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ جِبْرَائِيْلُ أَمَّا الْعَجُوْزُ الَّتِي رَأَيْتَ عَلٰى جَانِبِ الطَّرِيْقِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِ تِلْكَ الْعَجُوْزِ، وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَ أَنْ تَمِيلَ إِلَيْهِ، فَذَاكَ عَدُوُّ اللهِ إِبْلِيْسُ، أَرَادَ أَنْ تَمِيْلَ إِلَيْهِ وَأَمَّا الَّذِيْنَ سَلَّمُوْا عَلَيْكَ، فَذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ وَمُوْسَى وَعِيْسَى.(ابن جریر زیر آیت ھذا) ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کرکے لکھا ہے کہ وَ ھٰکَذَارَوَاہ الْحَافِظُ الْبَیْہَقِیُّ فِی دَلَائِلِ النُّبُوَّۃِ مِنْ حَدِیْثِ ابْنِ وَھْبٍ وَفِیْ بَعْضِ اَلْفَاظِہٖ نَکَارَۃٌ وَ غَرَابَۃٌ.طَرِیْقُ اُخْرٰی عَنْ اَنَسٍ ابْنِ مَالِکٍ وَفِیْھَا غَرَابَۃٌوَنَکَارَۃٌ جِدًّاوَھِی فِی سُنَنِ النَّسَائِی الْمُجْتَنیٰ وَلَمْ اَرَھَافِی الْکَبِیْرِ (ابن کثیرزیر آیت ھذا) یعنی ابن جریر انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا.جب جبرائیل ؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لائے تو اس نے اپنی دم ہلائی یعنی کچھ انکار کیا.تواسے جبرائیلؑ نے کہا آرام سے کھڑارہ.اے براق خدا کی قسم تجھ پرا یساسوار کبھی نہیں بیٹھا.تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ کرروانہ ہوئے.توراستے میں کیادیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا راستہ کی ایک جانب کھڑی ہے.توآپ نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے.توجبرائیل نے کہا.چلئے چلئے اے محمد ؐ!(یعنی موسیٰ کی طر ح سوال کرنے سے منع کیا )راوی کہتاہے پھر آپ چلے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کامنشاء تھا.توکیا دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص راستہ کی ایک جانب سے آپ کو بلارہا ہے اورکہتاہے کہ ادہر آئیے اے محمدؐ! اس پر جبرائیل نے پھر آپ کو بولنے سے منع کیا اورکہا کہ اے محمد ؐ چلئے چلئے اور کچھ جواب نہ دیجئے.پھر آپ آگے چلے جتنا کہ خدا کی مرضی تھی.راوی کہتاہے کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مخلو ق میں سے کچھ لوگ ملے.توانہوں نے کہا اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَااَوَّلُ.اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا اٰخِرُ.السَّلَامُ عَلَیْکَ یَاحَاشرُ.اس پرجبرائیل نے کہا.اے محمد ؐ ان کو سلام کا جواب دیجئے.توآپ نے ان کو سلام کا جواب دیا.پھر آپ کو ایسی ہی ایک اَور جماعت ملی.اس نے بھی پہلی جماعت کے الفاظ میں آپ کوسلام کہا.(پھرآپ آگے چلے)یہاں تک کہ آپ بیت المقدس تک پہنچے.توآپ کے سامنے حضرت جبرائیل نے تین پیالے پیش کئے ایک پانی کا.ایک دودھ کا اورایک شراب کا.اسراء میں دودھ سے مراد فطرت آپ نے دودھ لے کر پی لیا.توآپ کو جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت صحیحہ کوپالیا.اگرآپ پانی پی لیتے توآپ بھی غرق ہوتے اورآ پ کی امت بھی غرق ہوتی.اوراگرآپ شراب پی لیتے توآپ بھی گمراہ ہوتے اورآپ کی امت بھی گمراہ ہوجاتی.پھر آپ کےسامنے آدم اوردیگر انبیاء لائے گئے اوراس
Page 281
رات ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی.اسراء میں بڑھیا دیکھنے سے مراد دنیا پھر آپ کو جبرائیل نے کہا کہ جو بڑھیا آپ نے رستہ کے ایک جانب دیکھی تھی وہ دنیا تھی.اوراس کی عمر سے اسی قد رباقی ہے جوکہ اس بڑھیا کی عمر باقی ہے.اورجو شخص رستہ سے ہٹ کر آپ کو بلاتاتھا.تاآپ اس کی طرف مائل ہوں وہ خدا کادشمن ابلیس تھا.اوروہ لوگ جنہوں نے آپ کو السَّلَامُ عَلَیْکَ کہا وہ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ وغیر ہ تھے.یہاں تک ابن جریر کی روایت ختم ہوئی.اس کے بعد ابن کثیر کے حوالے سے جو عبارت لکھی گئی ہے اس کایہ ترجمہ ہے کہ حافظ بیہقی نے بھی دلائل النبوت میں ابن وہب سے یہی روایت بیان کی ہے مگراس میں بعض الفاظ قابل اعتراض ہیں اور دوسرے اسناد سے ان کی تصدیق نہیں ہوتی اورایک اَورسند کے ساتھ انہوں نے انس بن مالک سے یہی روایت کی ہے مگر اس میں بعض ایسی باتیں بیان کی ہیں جن کی دوسری احادیث سے تصدیق نہیں ہوتی.اوریہ روایت سنن نسائی کی ایک خلاصہ میں بھی میں نے دیکھی ہے.مگربڑی سنن نسائی میں وہ حدیث نہیں ملی.حدیث اسراء بروایت انس بطور معیار یہ وہ حدیث ہے جوہمارے لئے معیار کے طور پر ہے کیونکہ میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ صحیح اور سچی ہے.اوراس میں صرف ایک غلطی ہے.اوروہ یہ کہ جہاں پیالے پیش کرنے کا ذکر ہے وہاں پانی کے بعد دودھ اورپھر شراب کا ذکرکیا ہے مگرابن کثیر نے اس روایت کواپنی کتاب کی جلد ششم ص۸، ۹پر جس طرح نقل کیا ہے اس میں پانی کے بعد شراب اورپھر دو دھ کا ذکرکیا ہے.جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض نسخوں میں اسی ترتیب سے پیالوں کا ذکرکیا گیا ہے.میں آگے چل کربتائوں گاکہ اس معمولی تغیر کی اصلاح کیوں ضروری ہے اس وقت صرف یہ بتاناچاہتاہوں کہ بعض دوسری روایات میں زورسے اس امر کو بیان کیاگیاہے کہ پہلے پانی کاپیالہ اورپھر شراب کاپیالہ اورپھر دودھ کاپیالہ پیش کیاگیا تھا.چنانچہ الطبرانی اورابن مردویہ نے صہیب بن سنان سے روایت کی ہے جس کے یہ الفاظ ہیں.قَالَ لَمَّاعُرِضَ عَلٰی رَسُولِ اللہ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَیْلَۃَ اُسْرِیَ بِہِ الْمَاءُ ثُمَّ الْـخَمْرُ ثُمَّ اللَّبَنُ اَخَذَ اللَّبَنَ (خصائص الکبریٰ باب خصوصیَّتُہ صلی اللہ علیہ سلم حدیث صہیب صفحہ ۱۵۹) یعنی صہیب روایت کرتے ہیں کہ جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا ء ہواتھا.آپ کے سامنے تین پیالے پیش کئے گئے تھے.پہلے پانی کا اس کے بعد شرا ب کااوراس کے بعد دودھ کا.اس حدیث میں پانی کے بعد شراب اوراس کے بعد دودھ کے پیش ہونے کو بالجزم بیان کیاگیا ہے.پس اس
Page 282
حدیث کی بناء پر اورابن کثیر نے انس کی روایت کو جن الفاظ میں نقل کیا ہے.اس کی بنا ء پر یقین سے کہاجاسکتا ہے کہ اس روایت میں بھی پہلے پانی.پھر شراب پھردودھ کا ذکر ہے مگر بعض نسخوں میں الٹ لکھا گیاہے.پس میں اس روایت کے جومعانی بیان کروں گا.ان میں اس امر کومدنظررکھوں گا کہ اس روایت میں بھی پہلے پانی پھر شراب اورپھر دودھ کا ذکر ہے اوراس کے الٹ جولکھا گیاہے وہ کسی نسخہ میں کتابت کی غلطی کی وجہ سے سہواً لکھا گیا ہے.ابن کثیر کی تصدیق دُرّمنثورسے بھی ہوتی ہے.اس میں بھی اس روایت کو بیان کرتے ہوئے پہلے پانی پھر شراب پھر دودھ کے پیش کئے جانے کا ذکر ہے.جیساکہ میں نے اوپر بیان کیا ہے یہ روایت نہایت صحیح ہے اوراس کے صحیح ہونے کی اندرونی شہادت موجود ہے.اوروہ شہادت یہ ہے کہ ا س میں ذکر ہے کہ پہلے آپ نے ایک بڑھیا دیکھی پھر شیطان دیکھا پھرانبیاء کی جماعتوں کو دیکھا اس کے بعد بیت المقدس پہنچے.پھرپانی اورشراب اوردودھ تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں.رسول ا للہؐ نے پانی اورشراب کے قبول کرنے سے انکار کردیااوردودھ کولے لیا.اس پر جبرائیل نے کہا آ پ نے صحیح فطرت کوپالیا.اگرآپ پانی پیتے توغرق ہوجاتے اورآپ کی امت بھی غرق ہوجاتی.اگرشراب پیتے توآپ گمراہ ہوجاتے اورآپ کی امت بھی گمراہ ہوجاتی.اورآپ نے جودودھ لیا ہے گویاآپ فطرت صحیحہ کے راستہ پر چل پڑے.پھر وہ ان نظاروں کی تعبیر کرتے ہیں جوپہلے دیکھے تھے اورکہتے ہیں کہ وہ عورت دنیا تھی.جس نے آپ کوبلایا.اس کے بعدراستہ سے ہٹ کر کھڑاہواشخص جس نے آپ کو بلایا ابلیس تھا.اس کے بعد جنہوں نے سلام کیا وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے.اسراء میں پانی ،دودھ اور شراب پیش کئے جانےکی تعبیر ان تعبیروں کو دیکھو کہ کیسی صحیح ہیں اورقرآن کریم کے مطابق ہیں.پانی دنیا کاقائم مقام ہے کیونکہ پانی سے حیات ہوتی ہے.جیسے فرمایا وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.(الانبیاء :۳۱) پانی جب لَبن کے مقابل میں آئے تواس سے مراد دنیا کی مال و دولت ہوتی ہے.اور شراب شیطانی کاموں پر دلالت کرتی ہے جیسے فرمایا.اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ.(المائدہ :۹۱).دودھ ماں کی چھا تی سے بنتاہے اس میںکسی غیر چیز کی ملونی نہیں ہوتی اس لئے وہ فطرت صحیحہ پردلالت کرتا ہے.اس روایت کے واقعات میں طبعی ترتیب ہے اب دیکھو اس میں کیسی ترتیب نظرآتی ہے.پھر تعبیر نہایت صاف اورصحیح ہے.پہلے آپ نے عورت کودیکھا تھا.اوراس کی تعبیر جبرائیل علیہ السلام نے دنیا بتائی تھی.اس کے مقابل پر پہلے پانی کا پیالہ پیش کیا گیا.اوراس کی تعبیر بھی دنیا ہی کی گئی.قرآ ن کریم میں بھی پانی کو دنیا سے تشبیہ
Page 283
کہ قرآن کریم نے بھی اس کا نام رؤیا ہی رکھا ہے.جیسے اسی سور ۃ کے چھٹے رکوع میں فرمایا وَ مَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْۤ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ(بنی اسرائیل:۶۱).کہ یہ رؤیا لوگوں کے فتنے کے لئے تھی.چنانچہ ا س آیت کی وجہ سے کئی صحابہ اورسابق علماء نے بھی اسے رؤیاہی قرار دیا ہے.چنانچہ ابن اسحاق اورابن جریر نے حضرت معاویہؓ سے روایت کی ہے کہ اِذَاسُئِلَ عَنْ مَسْرٰی رسول اللہ ِصَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قال کانَتْ رُؤْ یَا منَ اللہِ صَادِقَةً.(درمنثورزیر آیت ھذا)یعنی جب حضر ت معاویہ ؓ سے اسراء کے متعلق پوچھاگیا توآپ نے فرمایاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رؤیاتھی جو پوری ہوگئی.حضرت عائشہؓ کا بھی یہی مذہب بتایاجاتاہے.(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام ذکرالاسراء حدیث عائشۃ عن مسراہ صلی اللہ علیہ وسلم وزاد المعادجلد ۳ فصل فی الاسراء والمعراج) (۳)تیسراثبوت اس کایہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات لوگوں کو سنائی.تولوگوں نے کہا کہ اگرآپ بیت المقدس سے ہوآئے ہیں تواس کانقشہ بتائیں.توآپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل بیت المقدس کو نہ جانتاتھا.اگرآنحضرت صلی اللہ علیہ سلم فی الحقیقت ظاہری طورپر بیت المقدس میں گئے تھے توآپ کو چاہیے تھا کہ آپ نقشہ بتادیتے.یہ تونہ فرماتے کہ میں نہ جانتا تھا.پھر آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ ان کے سوال کرنے کے بعد پھرمجھ پر کشف کی حالت طاری ہوئی.اورکشف میں بیت المقدس کا نقشہ سامنے کر دیا گیا.تومیں اس کو دیکھتاجاتاتھا اورپھر لوگوں کو بتاتاجاتاتھا.چنانچہ جابربن عبداللہ کی راویت ہے.آپ نے فرمایا.فَـجَلَّی اللہُ لِیَ الْبَیْتَ المَقْدِسِ فَطَفِقْتُ اُخْبِرُھُمْ واَنااَنْظُرُ اِلَیْہِ.کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کومیرے سامنے کردیا.میں اس کو دیکھتا اورلوگوںکوبتاتاجاتا تھا.(ابن کثیر زیر آیت ھذا) اس حدیث سے ظاہر ہے کہ چونکہ وہ کشف تھا آ پ سمجھتے تھے کہ ممکن ہے جومیں نے دیکھا ہے اس طر ح ظاہری طورپر نہ ہو.پس آپ نے اس کے بیان کرنے سے ہچکچاہٹ کی.مگرچونکہ اس واقعہ کے بیان کرنے سے لوگوں میں مخالفت اوراستہزاکاہیجان پیداہوگیاتھا.اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو اب ہم تم کواصل صورت میں بیت المقدس دکھادیتے ہیں.چنانچہ دوبارہ کشف ہو ااورآپ نے اس کے مطابق لوگوںکو بیت المقدس کانقشہ بتادیا.جس کی کفار میں سے واقف کار لوگوں نے تصدیق کی.متعصب عیسا ئی مصنف اس موقعہ پرلکھتے ہیں کہ بیت المقدس کے نقشے اس وقت بن چکے تھے(تفسیر قرآن از ویری جلد ۳ صفحہ ۵۶).ممکن ہے یہ درست ہو.مگرذرایہ مصنف کسی ایسے شہر کے متعلق نقشہ دیکھ کر جوان پر سوال کئے جائیں ان کا جواب تودے کر دیکھیں.
Page 284
کشف اور رؤیا کی تعریف میں فرق اس جگہ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گوقرآن کریم میں اس کے متعلق رؤیاکالفظ آیا ہے مگرا س لفظ سے دھوکا کھا کر اسے عام خوابوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے.کیونکہ عربی میں رؤیا کامفہوم اَورہے اوراردومیں اَور.اردومیں تورؤیا اس نظارہ کو کہتے ہیں جو انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے.لیکن عربی میں کشف اورعام خواب دونو ںکے لئے رؤیاکالفظ بولاجاتاہے.اورکشف عام رؤیا سے مختلف ہوتاہے.وہ سوتے میں نہیں دیکھاجاتا بلکہ بیَن النَّوم والیقظہ کی حالت میں دیکھاجاتاہے.یعنی جبکہ ایک ربودگی کی سی حالت توانسان پر طاری ہوتی ہے مگر وہ سونہیں رہاہوتا.بلکہ اس کے ظاہری حواس بھی اس وقت اپناکام کررہے ہوتے ہیں.بلکہ بعض دفعہ دوسرے سے باتیں کرتے کرتے ایک نظارہ نظرآجا تا ہے.انبیاء کاکشف دوسرے لوگوں کے کشوف سے زیادہ لطیف ہوتاہے اوروہ کشفی نگاہ سے دوردور کے مادی امورکو بعینہٖ معائنہ کرلیتے ہیں.کشف کی تین اقسام کشف کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں.(۱)ایسا کشف جس میں دکھائے جانے والے نظارے اسی شکل میں دکھائے جاتے ہیں.جس شکل میں کہ وہ مادی دنیا میں موجود ہوتے ہیں اوروہ کشف بالکل ایساہوتا ہے جیسے دوربین سے دورکی چیز دیکھ لی جاتی ہے.(۲)ایساکشف جس کا کچھ حصہ توایساہوتاہے جواوپر بیان ہواہے اور کچھ حصہ تعبیر طلب ہوتاہے.(۳)ایسا کشف جو ساراکاساراتعبیر طلب ہوتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کایہ کشف دوسری قسم کاتھا یعنی بعض حصے تو اسی طرح دکھائے گئے تھے جس طرح کہ مادی دنیا میں واقع ہورہاتھا.اوربعض حصے تعبیر طلب تھے.تعبیر طلب حصوںکا ذکرتو میں اوپر کرآیا ہوں.ظاہری شکل میں دکھائے جانے والے حصہ کے بارہ میں احادیث میں آتا ہے کہ واپسی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکہ کی طرف آرہاہے.اوراس قافلہ والوں کاایک اونٹ گم ہوگیا ہے جس کی وہ تلاش کررہے ہیں.اورچند دن بعد معلوم ہواکہ بعینہٖ یہ واقعہ مکہ کے ایک قافلہ سے پیش آیا تھا.چنانچہ جب وہ قافلہ مکہ پہنچا توانہوں نے اس امرکوتسلیم کیا.(الخصائص الکبریٰ حدیث شداد بن اوس جلد او ل ص ۱۵۸و۱۵۹) کشف کے متعلق ذاتی تجربہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کشوف کے متعلق خود صاحب تجربہ ہو ںاوریہ امور اپنے مشاہد ہ کی تصدیق سے لکھ رہاہوں.اسراء کے کشف سے غرض ہجرت تھی اب میں یہ بتاتاہوں کہ اس کشف کا مقصد کیا تھا ؟میرے نزدیک اس کشف میں ہجرت مدینہ کی خبر دی گئی تھی.اوربیت المقدس جو آپ کو دکھا یاگیا اس سے مراد مسجد نبویؐ کی تعمیر تھی.
Page 285
کشف اور رؤیا کی تعریف میں فرق اس جگہ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گوقرآن کریم میں اس کے متعلق رؤیاکالفظ آیا ہے مگرا س لفظ سے دھوکا کھا کر اسے عام خوابوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے.کیونکہ عربی میں رؤیا کامفہوم اَورہے اوراردومیں اَور.اردومیں تورؤیا اس نظارہ کو کہتے ہیں جو انسان سوتے ہوئے دیکھتا ہے.لیکن عربی میں کشف اورعام خواب دونو ںکے لئے رؤیاکالفظ بولاجاتاہے.اورکشف عام رؤیا سے مختلف ہوتاہے.وہ سوتے میں نہیں دیکھاجاتا بلکہ بیَن النَّوم والیقظہ کی حالت میں دیکھاجاتاہے.یعنی جبکہ ایک ربودگی کی سی حالت توانسان پر طاری ہوتی ہے مگر وہ سونہیں رہاہوتا.بلکہ اس کے ظاہری حواس بھی اس وقت اپناکام کررہے ہوتے ہیں.بلکہ بعض دفعہ دوسرے سے باتیں کرتے کرتے ایک نظارہ نظرآجا تا ہے.انبیاء کاکشف دوسرے لوگوں کے کشوف سے زیادہ لطیف ہوتاہے اوروہ کشفی نگاہ سے دوردور کے مادی امورکو بعینہٖ معائنہ کرلیتے ہیں.کشف کی تین اقسام کشف کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں.(۱)ایسا کشف جس میں دکھائے جانے والے نظارے اسی شکل میں دکھائے جاتے ہیں.جس شکل میں کہ وہ مادی دنیا میں موجود ہوتے ہیں اوروہ کشف بالکل ایساہوتا ہے جیسے دوربین سے دورکی چیز دیکھ لی جاتی ہے.(۲)ایساکشف جس کا کچھ حصہ توایساہوتاہے جواوپر بیان ہواہے اور کچھ حصہ تعبیر طلب ہوتاہے.(۳)ایسا کشف جو ساراکاساراتعبیر طلب ہوتا ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کایہ کشف دوسری قسم کاتھا یعنی بعض حصے تو اسی طرح دکھائے گئے تھے جس طرح کہ مادی دنیا میں واقع ہورہاتھا.اوربعض حصے تعبیر طلب تھے.تعبیر طلب حصوںکا ذکرتو میں اوپر کرآیا ہوں.ظاہری شکل میں دکھائے جانے والے حصہ کے بارہ میں احادیث میں آتا ہے کہ واپسی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکہ کی طرف آرہاہے.اوراس قافلہ والوں کاایک اونٹ گم ہوگیا ہے جس کی وہ تلاش کررہے ہیں.اورچند دن بعد معلوم ہواکہ بعینہٖ یہ واقعہ مکہ کے ایک قافلہ سے پیش آیا تھا.چنانچہ جب وہ قافلہ مکہ پہنچا توانہوں نے اس امرکوتسلیم کیا.(الخصائص الکبریٰ حدیث شداد بن اوس جلد او ل ص ۱۵۸و۱۵۹) کشف کے متعلق ذاتی تجربہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کشوف کے متعلق خود صاحب تجربہ ہو ںاوریہ امور اپنے مشاہد ہ کی تصدیق سے لکھ رہاہوں.اسراء کے کشف سے غرض ہجرت تھی اب میں یہ بتاتاہوں کہ اس کشف کا مقصد کیا تھا ؟میرے نزدیک اس کشف میں ہجرت مدینہ کی خبر دی گئی تھی.اوربیت المقدس جو آپ کو دکھا یاگیا اس سے مراد مسجد نبویؐ کی تعمیر تھی.
Page 286
جس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیت المقدس سے بھی زیادہ عزت دی جا نے والی تھی.اوریہ جو دکھا یا گیا کہ آپ نے سب انبیاء کی امامت کرائی اس میں یہ بتایاگیا تھا کہ آپ کا سلسلہ عربوں سے نکل کر دوسری اقوام میں بھی پھیلنے والا ہے اورسب انبیاء کی امتیں اسلام میں داخل ہوں گی.اوریہ اشاعت مدینہ میں جانے کے بعد ہوگی.اوراس میں اس طرف بھی اشار ہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے علاقہ کی حکو مت دی جائے گی.مسجد کو دیکھنے کی تعبیر چنانچہ تعبیر الرؤیا کی کتب میں لکھا ہے کہ تَدُلُّ رُؤْیَۃُ کُلِّ مَسْجِدٍ علٰی جِھَتِہٖ وَالتَّوَجُّہِ اِلَیْھَا کَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی وَالْمَسْجِدِ الْـحَرَامِ وَمَسْجِدِ دِمشْقَ وَمَسْجِدِ مِصْرَ وَمَاشَاکَلَ ذٰلِکَ وَرَبُّمَا دَلَّتْ عَلیٰ عُلَمَاءِ جِھَاتِھِمْ اَوْ مُلُوکِھِمْ اَوْ نُوَّابِ مُلُوْکِھِمْ(تعطیر الانام زیر لفظ مسجد.جلد دوم )یعنی رؤیا میں مسجد دیکھنے سے مراد کبھی و ہ جہت ہوتی ہے اوراس طرف جانامراد ہوتاہے.جیسے مسجد اقصیٰ کو دیکھنا یامسجد حرام کو دیکھنا یامسجد دمشق یامسجد مصر کو دیکھنا.اورایسے ہی اورمساجد کودیکھنا اور کبھی مسجد سے مراد وہاں کے علما ء یابادشاہ یاگورنر ہوتے ہیں.آنحضرت ؐ کے حق میں تعبیر کس طرح پوری ہوئی اب میں ایک ایک کرکے ان معنو ں کولیتاہوں کہ وہ کس طرح اورکس دلیل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پورے ہوئے.پہلی تعبیر میں نے یہ کی تھی کہ مسجد اقصیٰ سے مراد اس جگہ مسجد نبوی ؐ ہے.اوریروشلم سے مراد مدینہ ہےاور ادہر جانے سے مراد آپ کی ہجرت ہے.اوراللہ تعالیٰ نے سُبْحٰن کہہ کر اس رؤیا کا ذکرکیا ہے جس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کی سُبوحیت کااظہارکرنے والی ہوگی.یہ سبحان کالفظ بھی بتاتا ہے کہ اس نظارہ میں ایک پیشگوئی تھی کیونکہ ظاہر میں بیت المقدس کودیکھنے سے سبوحیت ثابت نہیں ہوتی.لیکن مدینہ میں جاکر اسلامی حکومت کاقیام چونکہ بہت سی ان پیشگوئیوں کوپوراکرنے والاتھا جوقرآن کریم میں بیان ہوچکی تھیں.اس واقعہ سے بے شک اللہ تعالیٰ کی سبوحیت ظاہر ہوئی تھی اوراب تک ہورہی ہے.غرض سُبْحٰنَ الَّذِيْۤ اَسْرٰى کہہ کرفرمایاکہ پا ک ہے وہ جولے جائے گا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجداقصیٰ یعنی اسی کے مشابہ ایک مسجد کی طرف تاکہ وہ پیشگوئیاں پوری ہوں جن کے لئے ہجرت کرنی ضروری ہے.اوراللہ تعالیٰ دنیا کو دکھادے کہ کس طرح اس کی بات پوری ہواکرتی ہے.مثلاً جنگ و جہاد وغیرہ کی خبریںجوہجرت کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں.پھرا سلامی حکومت کی خبر وغیرہ وغیرہ.لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا میں بھی ہجرت کی طرف اشارہ ہے لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا بھی اسی امر پردلالت کرتا ہے کہ
Page 287
یہ کوئی ایساسفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے خاص نشان ظاہر ہوں گے.اوروہ ہجرت ہی کاسفر تھا جس نے اسلام کامستقبل جودنیاکی نگاہ سے پوشیدہ تھا ایسے شاندار طورپر ظاہرکردیا.اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ میں بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے.کیونکہ بیت المقدس کو محض کشف میں دیکھ لینا خدا تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کاثبوت پیش نہیں کرتا لیکن مدینہ کی ہجرت ان دونوں صفات کا ثبوت پیش کرتی ہے.سَمِیْعٌ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے.بَصِیْرٌ اس طرح کہ جن کامیابیوں کی ہجرت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی گئی تھی وہ بعینہٖ پوری ہوگئیں.نیز ا س طرح کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جس طرح نگہداشت کی وہ ایک بصیر خداکے وجود کی بیّن شہادت تھی.اوریہ جو مسجد نبویؐ کو مسجد اقصیٰ کہاگیا اورمدینہ کو یروشلم کی شکل پر دکھایاگیا.اس کی وجہ یہ تھی کہ جوبرکات اس شہر کو اوراس مسجد کو ملی تھیں.وہی مسجد نبوی ؐ اورمدینہ منورہ کو ملنے والی تھیں.اگرکہا جائے کہ کیوں مسجد نبویؐ کو مسجد حرام سے تشبیہ نہ دی گئی اورمسجد اقصیٰ سے دی گئی ؟تواس کا جواب یہ ہے کہ اول تومسجد حرام کو بعض زائد خصوصیات حاصل ہیں جوارکان حج سے تعلق رکھتی ہیں.اوریہ خصوصیات بیت المقدس یامسجد نبوی کو حاصل نہیں.دوسرے بیت المقدس کو کشف میں دکھانے سے یہ بھی بتانا مقصود تھا کہ آپ کی امت ان علاقوں پرقابض ہوجائے گی.اوریہ مضمون مسجد حرام کے دکھانے سے ظاہر نہ ہوتا تھا.پس چونکہ ابھی بعض سیاسی وجوہ کی بناء پر وہ وقت نہ آیاتھا کہ اصل نام ظاہر کیا جاتا.اس لئے تشبیہاً مسجد نبوی کانام مسجد اقصیٰ رکھ دیا.اورمدینہ کو یروشلم کی شکل میں دکھایا.یہ پیشگوئی جس رنگ میں پوری کی گئی وہ ذیل کی روایت سے ظاہر ہے.عَنْ اَبِی ھُرِیْرَۃَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاتَشُدُّوْا الرِّحَالَ اِلَّا اِلٰی ثَلٰثَۃِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدِ الْـحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی.آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ سواری پرچڑھ کر کسی مسجد کی طرف نہ جانا چاہیے.سوائے تین مساجد کے ایک مسجد حرام.دوسری مسجد اقصیٰ اورتیسری مسجد نبوی ؐ(بخاری کتاب الجمعة باب فضلِ الصلوٰۃ فی مسجد مکۃ والمدینۃ) مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں مشابہت اس جگہ مسجد نبوی اورمسجد اقصی کو آپس میں مشابہت دی ہے.پس مسجد نبوی کی بنیادسے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی پیشگوئی پوری ہوگئی.اس مسجد کی طرف جانے کے علاوہ اس آیت میں ایک اور بات بھی بتائی گئی تھی.اوروہ یہ کہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جس کے اردگرد کوبھی برکت دی گئی ہے.یعنی جس شہر میں وہ ہے اسے بھی معززاور مکرم بنادیاگیا ہے.اس خبر کے مطابق نہ صرف مسجد نبوی کو برکت دی گئی بلکہ اس کے
Page 288
اردگرد کے علاقہ یعنی مدینہ کو بھی برکت دی گئی.اس کے مندر جہ ذیل ثبوت ہیں.آنحضرتؐ کی مدینہ میں ترقی کے لئے دعا (۱)بخاری میں روایت ہے کہ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْ لُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَللّٰھُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِیْنَۃِ ضِعْفَیْ مَاجَعَلْتَ بِمَکَّۃَ مِنَ الْبَرَکَـۃِ(بخاری کتاب فضائل المدینۃ باب المدینۃ تنفع الخبث )یعنی حضرت انس فرماتے ہیںکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاکی کہ اے اللہ مکہ میں جو تو نے برکت رکھی ہے اس سے بڑ ھ کر مدینہ میں برکت رکھ دے.(۲) اَللّٰھُمَّ حَبِّبْ اِلَیْنَا الْمَدِیْنَۃَ کَحُبِّنَا مَکَّۃَ اَوْاَشَدَّ اَللّٰھُمَّ بَارِکَ لَنَا فِی صَاعِنَا وَفِیْ مُدِّنَا.(بخاری کتاب فضائل المدینۃ باب المدینۃ تنفع الخبث) یعنی حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں.رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاکی کہ الٰہی تومدینہ بھی ہمیں ایسا ہی پیارابنادے جس طرح ہمیں مکہ پیاراہے بلکہ اس سے بھی زیادہ.اے اللہ اس کے صاع اورمُدّمیں برکت ڈال دے.یعنی اہل مدینہ کے گذارے کے لئے ان کی زراعت اورتجارت میں برکت دے.(۳)عَنْ زَیْدِ بْنِ عَاصِمٍ اَنَّ اِبْرَاھِیْمَ حَرَّمَ مَکَّۃَ وَدَعَالِاَھْلِھَاوَاِنِّیْ حَرَّمْتُ الْمَدِیْنَۃَ کَمَاحَرَّمَ اِبْرَاھِیْمُ مَکَّۃَ وَاِنِّیْ دَعَوْتُ فِیْ صَاعِھَا وَمُدِّھَا بِمِثْلَیْ مَادَعَابِہِ اِبْراھِیْمُ لِأَھْلِ مَکَّۃَ( مسلم کتاب الحج باب فضل المدینۃ).یعنی زید بن عاصم کہتے ہیں کہ رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ ابراہیمؑ نے مکہ کو محفوظ مقام قرار دیاتھا اوراس کے باشندوں کے لئے دعاکی تھی.اورمیں نے مدینہ کو محفوظ مقام قرار دیا ہے اورمیں نے دعاکی ہے کہ مدینہ کے صاع اورمُدمیں اس سے دگنی برکت رکھ دے جتنی کہ ابراہیم نے مکہ کے لئے طلب کی تھی.(اس سے معلوم ہوتاہے کہ مدینہ کی فضیلت کے لئے جو دعاہے وہ دنیوی ترقی کے لئے ہے ورنہ آسمانی برکت کے لحاظ سے مکہ ہی سب دنیا کے شہروں سے افضل ہے ) ان روایات سے ظا ہر ہے کہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کاعلاقہ بھی بابرکت کیا گیا.اس سے مراد رؤیا میں درحقیقت مسجد نبوی تھی.اورہر عقلمند سوچ سکتاہے کہ مدینہ کوجو برکت ملی ہے کیا اس کا دسواں حصہ بھی یروشلم کو نصیب ہوئی ہے؟ اسریٰ کے لفظ میں بھی مجبوری سے سفر کا ثبوت ملتا ہے یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ سے ظاہر ہوتاہے کہ چلانے والا کوئی دوسرا تھا.اوراس میں چلنے والے کااپنا اختیا ر نہ تھا.ہجرت کاواقعہ بھی اسی طرح ہواکہ آپ رات ہی کونکلے.اوریہ نکلنا اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اس وقت مجبور ہوکر آپ نکلے جبکہ کفار نے آپ کے قتل
Page 289
کرنے کے لئے آپ کے گھر کامحاصرہ کرلیاتھا.پس اس سفر میں آپ کی مرضی کادخل نہ تھا.بلکہ خدا تعالیٰ کی مشیت نے آپ کو مجبورکیا.پھر جس طرح رؤیا میں جبریل بیت المقدس کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے.ہجرت میں ابوبکرؓ آپ کے ساتھ تھے.جوگویا اسی طرح آپ کے تابع تھے جس طرح جبریل خدا تعالیٰ کے تابع کام کرتا ہے.اور جبریل کے معنے خدا تعالیٰ کے پہلوان کے ہوتے ہیں.حضرت ابو بکر بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بند ے تھے اوردین کے لئے ایک نڈ رپہلوان کی حیثیت رکھتے تھے.مدینہ کے پہلے نام یثرب کی وجہ تسمیہ مدینہ کو جو برکت دی گئی اس کی ایک ظاہری صورت بھی تھی.اس کی حقیقت حضرت عائشہؓ کی ایک روایت سے ظاہر ہوتی ہے.آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ میں آپ کی آمد سے پہلے بخار کی وباء سخت پھیلاکرتی تھی جب آپ وہاں تشریف لے گئے توآپ کی دعا کے طفیل سے وہ وباء دور ہوگئی.اسی وباء کی وجہ سے پہلے مدینہ کانام یثرب تھا.کیونکہ یثرب کے معنے رونا پیٹنا ہے.مگرآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاکی وجہ سے وہ وباء دورہوگئی اورآئندہ یثرب کی بجائے آپ نے اس کانام مدینہ رکھا.(بخاری کتاب فضائل المدینۃ باب المدینۃ تنفی الخبث).اسلامی حکومت کی ترقی کا راز مدینہ کو مرکز قرار دینا تھا پھر کشف میں جو یہ دکھایاگیاتھا کہ مسجد اقصیٰ میں جاکر آپ نے تما م انبیاء کو نماز پڑھائی.یہ خبر بھی مدینہ میں جاکر پوری ہوئی اوراس مقام سے ہی اسلام کی اشاعت ساری دنیا میں ہوئی.بلکہ اس امر کو دیکھ کرحیرت آتی ہے کہ جب مدینہ سے اسلامی دارالخلافہ کو بدل دیا گیا ،اسی وقت سے اسلام کی ترقی رک گئی.تیس سال کے عرصہ میں جس میں مدینہ اسلامی دارالخلافہ تھا اس قدر اسلام کوترقی ہوئی اوراس قدر اس کی اشاعت ہوئی کہ اس کے بعد تیرہ سوسال میں اس قدرنہیں ہوئی.اگرکہو کہ یہ برکات توخود رسول کریم صلعم نے دی تھیں.تواس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کی برکات کوئی انسان نہیں دے سکتا انسان میں کہاں طاقت ہے کہ ایسی پیشگوئی کرے اوراس کو پوراکردکھائے.آپ نے جودعاکی وہ اللہ تعالیٰ کی اس پیشگوئی کی تائید میں تھی.اسراء میں مسلمانوں کے ملک شام پر قبضہ کرنے کی پیشگوئی (۲)دوسری صورت میں نے یہ بتائی تھی کہ مسجد اقصیٰ سے مراد بنی اسرائیل والی مسجد اقصیٰ بھی ہے اس صورت میں یہ تعبیر ہوگی کہ آپ کو اس ملک پر قبضہ دیا جائے گا.چنانچہ یہ تعبیر بھی پوری ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ کے وقت میں اس جگہ پر مسلمانوں کاقبضہ ہوگیا اورتیرہ صدیوں تک قبضہ رہا.اب عارضی طورپر یہ علاقہ عیسائیوں کے قبضہ میں چلا گیاہے.
Page 290
مگریہ بھی ایک پیشگوئی کے ماتحت ہے.اس کا زمانہ ختم ہونے پر پھر یہ ملک واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے ہاتھ میں آجائے گا.خواہ بہت جلد خواہ کچھ وقفہ کے بعد اس صورت میں راتوں رات وہاں جانے کے یہ معنے لئے جائیں گے کہ بیت المقدس کی فتح ظاہری جنگوں کے سبب سے نہ ہوگی بلکہ اس رات کے دیکھے ہوئے نظارہ کی وجہ سے ہوگی.چنانچہ واقعہ بھی یہی ہے ورنہ عربوں کا ایک چھوٹاسالشکر قیصر جیسے بڑے بادشاہ کامقابلہ کب کرسکتا تھا.یہ توالٰہی کلام جو سورۃ اسراء والی رات میں ناز ل ہواتھا اسی کااثر تھا کہ بے سروسامان عربوںکے سامنے قیصر کاباسامان اورفنون حرب کی تعلیم پایا ہوالشکر اس طرح بھاگتاجاتاتھا جیسے شیر کے سامنے ہوں.اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ ملک توحضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتح ہواتھا.تواس کا جواب یہ ہے کہ نبی کے اتباع پیشگوئیوں میں اسی کے وجود میں شامل سمجھے جاتے ہیں اوراس کی مثالیں کثرت سے اسلام اورپہلے انبیاء کے لٹریچر میں پائی جاتی ہیں.مسجد اقصیٰ کو دیکھنے سے عیسائیت اور یہودیت پر اقتدار کی طرف اشارہ (۴)چوتھی بات تعبیر الرؤیاء کے مطابق میں نے یہ بتائی تھی کہ علاقہ کے علماء بھی مسجد کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں اس تعبیر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک پر نہ صرف سیاسی قبضہ مسلمانوں کوحاصل ہوا بلکہ مذہباً بھی اکثر حصہ ملک کامسلمان ہوگیا او ر تیر ہ سوسال میں یروشلم اسلامی علماء کا مرکز بنارہاہے.یہ تغیرپیداکرنا بھی کسی انسان کی طاقت میں نہ تھا اللہ تعالیٰ ہی ایساکرسکتاتھا.آنحضرت ؐ کے واقعہ اسراء اور موسیٰ کے سفر میں فرق یہ عجیب بات ہے کہ موسیٰ کو بھی ایک نظارہ دکھایا گیا تھا اوراس کے متعلق جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی اس واقعہ کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں.حضرت موسیٰ ایک سفر پر تھے کہ انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی تواللہ تعالیٰ نے فرمایا بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَهَا١ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (النمل :۹)کہ جو اس آگ میں پڑے گا وہ بھی بابرکت اورجو اس کے گرد آکر بیٹھے گاوہ بھی بابرکت ہوگا اور وہ آگ محبت الٰہی کی آگ تھی اورپھر جس طرح وہاں سبحان کالفظ آیا تھااسی طرح اس جگہ سبحان بھی آیا ہے.اورجس طرح وہاں حَوْلَہُ آیا ہے اسی طرح یہاں بھی بَارَکْنَا حَوْلَہُ فرمایا ہے بعض نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آگ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے (قرطبی زیر آیت بورک من فی النار)مگر یہ غلط ہے.کیونکہ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آگ میں ہے اسے برکت دی گئی ہے.پس آگ سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ محبت الٰہی ہے اوریہ بتایاہے کہ جو محبت الٰہی کی آگ میں اپنے آپ کو ڈا ل دے اُسے برکت دی جاتی ہے محبت کو دنیا کی کل زبانوں میں آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے.بات یہ ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ اپناجلال دکھاتا ہے اس کو برکت دیتا ہے اوروہاں سے اس کی
Page 291
سبوحیت کاظہور ہوتاہے.اوران دونوں نظاروں میں یعنی اس میں جو موسیٰ نے دیکھا اور اس میں جو آنحضرت صلعم نے دیکھا ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ ہے.حضرت موسیٰ کاایک اورواقعہ بھی اس واقعہ سے ملتاہے اوروہ وہ واقعہ ہے جو اگلی سور ۃ کہف میںبیان ہواہے اس کی اس واقعہ سے جو مشابہت ہے اس جگہ پر بیان کی جائے گی.اسراء میں آنحضرت ؐ کی بعثت ثانی کی پیشگوئی میرے نزدیک اس کشف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روحانی سفر کی طرف بھی اشار ہ ہے اوریہ بتایا ہے کہ جب اسلام پرتاریکی کا زمانہ آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپؐ کے تابع وجود کے واسطہ سے پھر دنیا کی ہدایت کے لئے مقرر کرے گا.اوراس تابع کے واسطہ سے وہی برکات مسلمانوں کوپھر ملیں گی جوانبیاء بنی اسرائیل کو اور ان کے اتباع کو ملی تھیں اسی کی طرف سورئہ جمعہ میں بھی اشارہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ١ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.وَّ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ١ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ(الجمعة :۳،۴)یعنی خداہی ہے جس نے امیوں میں ان میں سے ہی رسول بھیجا ہے جو ان سے اللہ تعالیٰ کے نشانات بیان کرتاہے اورکتاب اورحکمت سکھاتا ہے اورانہیں پاک کرتا ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلاتھے.اسی طرح آنحضر ت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اورجماعت کوبھی دین سکھائیں گے جو اب تک ان مسلمانوں سے نہیں ملی بلکہ آیندہ زمانہ میں ظاہر ہوگی اوریہ با ت اللہ تعالیٰ سے بعید نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ غالب ہے اوروہ حکمت والا ہے یعنے یہ نہیں برداشت کرسکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تباہ ہو اور و ہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بعثت کرکے اس کی اصلاح نہ کرے.وَ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اورہم نے موسیٰ کو(بھی)کتاب دی تھی اوراس (کتاب )کوہم نے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت (کاذریعہ ) اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًاؕ۰۰۳ بنایاتھا(اوراس میں انہیں حکم دیاتھا)کہ تم میرے سواکسی کو (اپنا )کارساز نہ ٹھہرائو.حلّ لُغَات.ھُدًی:ھُدًی ھدٰی کامصدر ہے اورھَدَی کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر ۲۸.یَھْدِی ھَدَی سے ہے اور ھَدَاہٗ الطَّرِیْقَ وَاِلَیْہِ وَلَہٗ کے معنے ہیں بَیَّنَہٗ لَہٗ وَعَرَّفَہٗ بِہٖ.راستہ دکھایا ، بتایا
Page 292
اور واضح کیا.ھَدٰی فُلَانًا: تَقَدَّمَہٗ اس کے آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لے گیا.ھَدَاہٗ اللہُ اِلَی الْاِیْمَانِ: اَرْشَدَہٗ إِلَیْہِ.ایمان کی طرف رہنمائی کی.(اقرب) بنی اسرائِیْل اِسْرَائِیْلُ حضر ت یعقوب کالقب ہے (پیدائش باب۳۲.آیت ۲۸) اور بنواسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد کو کہتے ہیں.دُوْن دُوْنَ کے معنی ہیں.سِوَا.مزید تشریح کے لئے دیکھو نحل آیت نمبر ۸۷.وَکِیْلًا وَکِیْلًا کے معنی کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۱۰۹.اَلْوَکِیْلُ.المَوْکُوْلُ اِلَیْہِ جس کے سپرد کوئی بات کر دی جائے.وَقَدْ یَکُوْنُ لِلْجَمْعِ وَالْاُنْثٰی.یہ لفظ واحد و جمع ہر دو کے لئے اور اسی طرح مذکر و مؤنث ہر دو کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.وَیَکُوْنُ بِمَعْنٰی فَاعِلٍ اِذَا کَانَ بِمَعْنَی الْحَافِظِ اور جب اس کے معنی حافظ یعنی نگہبان کے ہوں توا س وقت اسم مفعول کے معنی میں نہیں بلکہ اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے.وُصِفَ بِہِ اللہُ تَعَالٰی اور انہی معنوں میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے.وَقِیْلَ الْکَافِی الرَّازِقُ اور بعض کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے اور رازق کے ہوتے ہیں.(اقرب) تفسیر.اٰتَيْنَا سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا ذکر اس آیت سے حضرت موسیٰ اوران کی قوم کا ذکرشروع کیا ہے ان آیات کاگذشتہ آیت اورپہلی سورۃ سے کئی طرح تعلق ہے (۱)پہلی آیت میں رسول کریم صلعم اورآپؐ کے اتباع کو بیت المقدس دینے کاوعدہ کیاگیاتھا.یہ شہر اوراس کے گرد کاملک پہلے الٰہی وعدہ کے مطابق حضرت موسیٰ اوران کی قوم کو ملا تھا.مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ کرکے اسے کھودیا.پس ان کے واقعہ کو یاد کراکے مسلمانوں کوتوجہ دلائی گئی ہے کہ موسوی قوم کی اچھی میرا ث تم کودی جارہی ہے مگرہوشیار رہنا.ایسانہ ہو.بُری میراث بھی لے لواورتباہ ہوجائو.یہود کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ اسلام سے وابستگی ہے (۲)سورئہ نحل کے آخر میں یہود سے تعلق پیدا ہونے کی پیشگوئی کی گئی تھی.اورہدایت کی تھی کہ ان سے عمدہ رنگ میں بحث کرنا.یعنی وہ ایک اہل کتاب قوم ہے ان سے مسلمّہ اصول کے مطابق اوران دلائل کے مطابق جوان کی کتب میں مذکور ہیں بحث کرنا.اب اس طریق بحث کی مثال پیش کرتا ہے یعنی ان کی کتاب سے ہی وہ پیشگوئیا ں پیش کرتاہے جن سے ان کے بگڑ جانے کی خبر اورعذاب الٰہی میں مبتلاہونے کی خبر ملتی ہے.اوربتاتاہے کہ ان حالات میں یہود کے لئے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ
Page 293
اس نئے عہد کو قبول کرکے اس عذاب کودور کریں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہواہے اوراگر ارض مقدس بحیثیت یہود ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے توبحیثیت مسلمان وہ اس میں پھر سے داخل ہوجائیں اس کے سوا ان کے لئے اورکوئی ترقی کی راہ کھلی نہیں ہے.ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ١ؕ اِنَّهٗ كَانَ (اوریہ بھی کہا تھا کہ اے )ان لوگوںکی نسل جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی پر )سوار کیا تھا و ہ عَبْدًا شَكُوْرًا۰۰۴ یقیناً(ہمارا)نہایت شکر گذا ربندہ تھا.حلّ لُغَات.ذُرِّیّۃ.ذُرِّیَّۃٌکے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۸۴.الذُّرِیَّۃُ: اَلصِّغَارُ مِنَ الْاَوْلَادِ وَاِنْ کَانَ قَدْ یَقَعُ عَلَی الصِّغَارِ وَالْکِبَارِ مَعًا فِی التَّعَارُفِ.یعنی ذریۃ کے معنی چھوٹی عمر کے بچوں کے ہوتے ہیں.لیکن کبھی عرف عام میں چھوٹے اور بڑے سب بچوں کے لئے مشترک طور پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے.وَیُسْتَعْمَلُ لِلوَاحِدِ والْجَمْعِ وَاَصْلُہُ الْـجَمْعُ.اور یہ لفظ ایک بچہ کے لئے بھی اور زیادہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے.گو اصل میں جمع کے لئے ہی یہ لفظ بنا ہے.(مفردات) شکور: شَکُوْرٌ شَکَرَ سے مبالغہ کاصیغہ ہے.اورشکر کے معنی کے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر ۶.شَکُوْرٌ شَکَرَ سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور شَکَرَ کبھی بغیر صلہ اور کبھی’’ ل‘‘ کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے.یعنی شَکَرَہٗ وشَکَرَلَہٗ اور اگر شَکَرَ کا’’ ل‘‘ صلہ آئے تو یہ زیادہ فصیح سمجھا جاتا ہے اور شَکَرَہٗ وَشَکَرَلَہٗ کے معنے یہ ہوتے ہیں اَثْنٰی عَلَیْہِ بِمَا اَوْلَاہُ مِنَ الْمَعْرُوْفِ.کہ کسی کے احسان کے باعث اس کی تعریف کی.گویا اقرارِ احسان اظہارِ قدر کے ساتھ شکر کہلاتا ہے اور کثرت کے ساتھ اقرارِ احسان کرنے والے کو شکور کہتے ہیں.تفسیر.یعنی اس کتاب کے نزول کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ اے نو ح کے ساتھیو ں کی ذرّیت تمہارادادانو ح توبڑاشکر گذار بند ہ تھا یعنی تم بھی اپنے با پ کے سپو ت بننااورشکر گذار بننے کی کوشش کرنا.بعض نے اس قو ل کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر محمول کیا ہے(فتح البیان زیر آیت ھذا).مگر میرے نزدیک یہ موسیٰ کی قوم ہی کے متعلق ہے.کیونکہ اس آیت کے بعد بھی پھر موسیٰ کی قوم کا ذکر شرو ع ہو جاتا ہے.ان
Page 294
الفاظ میں بنی اسرائیل کو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جس طرح نو ح کو ہم نے طوفان سے بچایا تھا تم کو سمند ر سے نجات دی ہے.پس نو ح اوران کے ساتھیو ںکی طرح تم بھی شکر گذار بنو.مسلمانوں کو مخالفت کے طوفان سے نجات دینے کی پیشگوئی اس آیت میں مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ایک مخالفت کے طوفان سے ہم تم کو نجات دینے والے ہیں.تم بھی ا س کی قدرکرنا.امت محمدیہؐ اورموسوی میں یہ فرق ہے کہ موسیٰ کی امّت نے شکر گذاری سے کام نہ لیا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نے شکر گذاری کا بے نظیر نمو نہ دکھایا.گوکچھ عرصہ بعد میںمسلمانوں نے بھی ناشکری کانمونہ دکھایااوراسی کی طرف درحقیقت ان آیات میں توجہ دلائی گئی ہے.وَ قَضَيْنَاۤ اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي اورہم نے اس کتاب میں بنی اسرائیل کویہ بات (کھول کر )پہنچادی تھی کہ تم یقیناًاس ملک میں دوبار فساد کروگے.الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا۰۰۵ اوریقیناً تم بہت بڑی سرکشی (اختیار )کروگے.حلّ لُغَات.قَضَیْنَا.قَضَیْنَا قَضٰی(یَقْضِیْ)سے جمع متکلم کاصیغہ ہے.اورقَضَی الشَّیْءَ کے معنی ہیں اَعْلَمَہٗ وبَیَّنَہٗ.کسی چیز کو خوب کھو ل کر بتایا(اقرب)پس قَضَیْنَا کے معنے ہوں گے.اَعْلَمَنَا وَاَخْبَرْنَا.ہم نے یہ بات کھول کر بتادی.قَضَی کی مزید تشریح کے لئے دیکھو حجر آیت نمبر۶۷.قَضَیْنَا قَضٰی سے جمع متکلم کاصیغہ ہے اورقَضٰی بَیْنَ الْخَصَمَیْنِ کے معنی ہیں حَکَمَ وَفَصَلَ.مدعی اورمدعاعلیہ کے درمیان جھگڑے کافیصلہ کردیا.قَضَی الشَّیْءَ قَضَاءً:صَنَعَہٗ بِاِحْکَامٍ وَقَدَّرَہٗ.کسی چیز کو عمدہ طورپر بنایا.اورا س کاصحیح اندازہ لگایا.قَضَی الْاَمْرَ عَلَیْہِ :خَتَمَہٗ وَاَوْجَبَہٗ وَاَلْزَمہٗ بِہٖ.اس کے خلاف بات کو ختم کردیا اوراس پر اس کوواجب کر دیا اوراس کاپوراکرنا ا س کا فرض قرار دیا.الشَّیءَ:اَعْلَمَہٗ وَ بَیَّنَہُ کسی معاملہ کا اعلان کیا اور اس کو کھول کر بیان کیا.قَضٰی لَکَ الاَمْرَاَیْ حَکَمَ لَکَ کسی معاملہ کاتیرے حق میں فیصلہ کردیا (اقرب) وَلَتَعْلُنَّ.وَلَتَعْلُنَّ عَلَا (یَعْلُوْ)سے مضارع کاصیغہ ہے.اورعَلَاالشَّیْءُ کے معنے ہیں اِرْتَفَعَ.کوئی چیز بلند ہوئی.علَافُلَانٌ فِی الْاَرْضِ.تَکَبّرَوَتَجَبَّرَ.اس نے تکبر اورسرکشی کی.عَلَا فُلَانًا :غَلَبَہُ وَ قَھَرَہُ کسی پر
Page 295
غالب آیا.عَلَا فُلَانًابِالسَّیْفِ ِ:ضَرَبَہُ.اسے تلوارماری.عَلَاالْمَکَانَ.صَعِدَہُ.کسی جگہ پر چڑھا.عَلَا فِی الْمَکَارِمِ.شرف خوبیوں میں ممتازہوا (اقرب) پس وَلَتَعْلُنََّّ کے معنے ہوں گے.کہ تم سرکشی کروگے.تفسیر.مسلمانوں کے لئے یہود سے عبرت حاصل کرنے کا موقعہ فرمایا کہ تمہارا نبی مثیل موسیٰ قراردیاگیا ہے اوراس مشابہت کو پوراکرنے کے لئے اسے بیت المقدس اوراس کے گرد کا علاقہ دیاجانے والا ہے.پس تم کو اس امر میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو کچھ بنی اسرائیل سے بعدمیں معاملہ ہواوہ تم سے نہ ہو اورو ہ واقعہ یہ بیان فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق ہم نے خبر دی تھی کہ دودفعہ تم دنیا میں عظیم الشان فساد کے مرتکب ہوگے.اورسخت مظالم کرو گے اور تم کو اس کی سزا میں تباہ کردیاجائے گا.گوسزادینے کا یہاں لفظاً ذکر نہیں کیا گیا.لیکن اگلی آیت سے یہ مضمو ن ظاہر ہے.اس آیت سے دو امور کا ثبوت اس آیت سے مندرجہ ذیل امور نکلتے ہیں(۱)اس میں قَضَیْنَا فی الْکِتٰبِ کے الفاظ ہیں.جن سے مراد حضرت موسیٰ کی کتاب ہے (۲)اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے دودفعہ باغی ہو کر الٰہی عذاب میں مبتلاہونے کی خبر اس کتاب میں پہلے سے دےدی گئی تھی.نئے اورپرانے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں دوغلطیاں کی ہیں.اول تویہ کہ بنی اسرائیل کی تباہی کے بعض واقعا ت تودرج کردئے ہیں.لیکن قرآنی الفاظ کی صداقت کے اظہارکے لئے وہ پیشگوئی درج نہیں کی.جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے.دوم جنہوں نے پیشگوئی بیا ن کرنے کی طرف توجہ کی ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیشگوئی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بیان کی گئی تھی.میں نے ان دونوں امور کو مدنظر رکھا ہے اورموسیٰ کی کتب سے پیشگوئیاں بیا ن کی ہیں اورواقعات تاریخی جمع کرکے لکھے ہیں.عَلَا کے معنی عَلَا بمعنے ظلم ہے یعنی تم لوگوں کے اوپر ظلم کروگے جبر کرنے لگ جائو گے اورتکبرکرو گے اور ظلم سے کام لو گے.کیونکہ عَلَا (یَعْلُوْ.عَلُوًّا) فُلَانٌ کے معنی ہوتے ہیں.تَکَبَّرَ وَتَجَبَّر یعنی تکبر کیا اورظلم سے کام لیا.وَعَلَا فُلَانًا بِالسَّیْفِ :ضَرَبَہٗ.اس کو تلوار سے مارا.یہود کی تباہی کا ذکر بائیبل میں فِی الْکِتٰبِ.کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اس کا ذکر موسیٰ کی کتاب میں ہے.چنانچہ موسیٰ کی کتاب میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے استثناء باب ۲۸.آیت ۱۵میں لکھا ہے ’’لیکن اگر تُو خداوند اپنے خدا کی آواز کاشنوانہ ہو گا کہ اس کے سارے شرعوں اورحکموں پر جو آج کے دن مَیں تجھے بتاتاہوںدھیان رکھ کے عمل
Page 296
کرے توایسا ہوگا کہ یہ ساری لعنتیں تجھ پر اتریں گی اورتجھ تک پہنچیں گی.‘‘اس کے بعد ان لعنتوں کا ذکر کیا ہے جونافرمانی کی وجہ سے ان پر اتریں گی.چنانچہ فرماتا ہے ’’خداوند تجھ کواور تیرے بادشاہ کو جسے تواپنے اوپر قائم کرےگا ایک گروہ کے درمیان جس سے تُو اورتیرے باپ دادے واقف نہ تھے لے جائے گا.‘‘آیت ۳۶.پھر لکھا ہے.’’خداوند ایک گروہ دور سے زمین کی انتہاسے ایساجلد بلکہ جیسا عقاب اُڑتا ہے تجھ پر چڑھالائے گا و ہ ایک گروہ ہوگی جس کی زبان تونہ سمجھے گا وہ ترشرو گروہ ہو گی جونہ بوڑھے کاادب نہ جوان پر کرم کرے گی اورو ہ تیر ی مواشی کاپھل اورتیری زمین کاپھل کھاجائےگی یہاںتک کہ توہلاک ہو جائے گا.اس لئے کہ غلّے اورمَے اور تیل اورتیری گائے بیل کی بڑھتی اوربھیڑ بکری کے گلّوں سے تیرے لئے کچھ نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ وہ تجھے فناکردے گی اوروہ تجھے تیرے سب پھا ٹکوں میں آ گھیرے گی یہاں تک کہ تیری اونچی اورمحکم دیواریں جن کا تجھے اپنے سارے ملک میں بھروساتھا گرجائیں گی اوروہ تجھے اس ساری زمین میں جسے خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا ہے ہرایک شہر کے سب پھاٹکوں میں آگھیر ے گی.اورتواپنے ہی بدن کا پھل ہاں اپنے بیٹوں اوراپنی بیٹیوں کاگوشت جنہیں خداوند تیرے خدا نے بخشا تھا اس محاصرہ کے وقت اوراس تنگی میں جو تیرے بیریوں کے سبب سے تجھ پر ہوگی کھائے گاوہ شخص جو تم میں نرم دل اوربہت ناز پروردہ ہو گا اس کی بھی نظر اپنے بھائی کی طرف اور اپنی ہمکنار جو روکی طرف اوراپنے باقی لڑکوں کی طرف جنہیں اس نے چھوڑ دیاہو گا بری ہو گی یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کے گوشت میں سے جسے وہ کھائے گاانہیں ان میں سے کسی کو کچھ نہ دے گا کیونکہ اس محاصرے اورتنگی میں جوتیرے دشمنو ں کے باعث سے تیرے سارے پھاٹکوں میں تجھ پر ہوگی اس کے لئے کچھ نہ باقی رہے گااوروہ عورت بھی جو تمہارے درمیان نرم دل اورنہایت نازنین ہو گی ایسی کہ نزاکت اورنرمی سے اپنے پائوں کاتلو ازمین پر لگانے کی جرأت نہیں رکھتی اس کی نظر اپنے ہمکنارشوہر کی طرف اوراپنے بیٹے کی طرف اوراپنی بیٹی کی طرف بُری ہوگی.‘‘ آیت ۴۹تا۵۶.پھرلکھا ہے :.’’اوریوں ہو گا کہ جس طرح خداوند نے تم سے خوش ہو کر تمہارے ساتھ نیکی کی اور تمہیں بہت کردیا اسی طرح خداوند تمہاری بابت خوش ہوگا کہ تمہیں ہلاک کرے اورنیست و نابود کرڈالے اورتواس سرزمین سے جس کاتومالک ہونے جاتا ہے جڑھ سے اکھا ڑ ڈالا جائے گا.اورخداوند تجھ کو سب قوموں کے درمیان زمین کے اس سرے سے اس سرے تک تِتّربتّرکرے گا اوروہاں تُو غیر معبودوں کی جو لکڑیا ںاورپتھر ہیں جس سے نہ تُونہ تیرے باپ دادے واقف تھے پر ستش کرے گا.‘‘آیت ۶۳و۶۴.
Page 297
ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ احکام الٰہی کو توڑ دیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک غیر قوم دور سے ان پر چڑھ آئے گی.اوران کا محاصرہ کرے گی.محاصرہ کے وقت قحط اوروباء پڑیں گے.آخر ان کے شہروں کی فصیلیں توڑ دی جائیں گی بادشاہ قید کرکے لے جایا جائے گا.اورقوم جلا وطن کرکے دور علاقوں میں بھیج دی جائے گی.یہ پیشگوئی ان دوفسادوں میں سے جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے پہلے فساد کی نسبت ہے.قضا کے معنی یہ جو فرمایا قَضَيْنَاۤ اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے ایک وحی کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو آئندہ آنیوالی اس مصیبت سے خبر دے دی تھی مگرافسوس کہ وہ پھر بھی ہوشیار نہ ہوئے.انسان کو ہوشیار کرنے کے دو مقصد دراصل پہلے بتانے سے غرض ہوشیارکرناہی ہوتاہے اورہوشیا رکرنے کے دومقصد ہوتے ہیں.(۱)انسان کوشش کرے اوربچ جاوے.(۲)اگر نہ بچے تواس پر حجت پوری ہو.آنحضرت ؐ کا اپنی امت کو ہوشیار کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے متعلق فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ (بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ باب قول النبی لتتبعن سنن من کان قبلکم )کہ تم پہلے لوگوں کے طریقہ پر عمل کروگے.اوربعض احادیث میں ہے کہ یہود و نصاریٰ کے نقش قدم پرچلو گے مگر افسوس کہ باوجود ہوشیارکردینے کے مسلمان بھی اس آفت سے نہ بچے.فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَاۤ اُولِيْ اورجب ان دو(بارکے فسادوں)میں سے پہلی(بار)کاوعدہ (پوراہونے کا وقت )آیا.توہم نے اپنے بعض ایسے بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ وَ كَانَ وَعْدًا بندوں کو (تمہاری سرکوبی کے لئے )تم پر (مستولی کرکے )کھڑاکردیا.جوسخت جنگ جو تھے اوروہ مَّفْعُوْلًا۰۰۶ (تمہارے)گھروںکے اند رجاگھسے.اور یہ (وعدہ بہرحال)پوراہوکر رہنے والاوعدہ تھا.حلّ لُغَات.اُوْلِی بَاسٍ.اُولُوْ جمع ہے جس کے معنے ذَوُوْ کے ہیں (یعنی فلاں صفت والے ) اس
Page 298
کامفرد نہیں آتا.بعض کہتے ہیں کہ یہ اسم جمع ہے.اوراس کامفرد ذُوْہے.جیسے غَنَمٌ اسم جمع ہے.اورشَاۃٌ اس کامفرد ہے.(اقرب)اَلْبَأْسُ:اَلْعَذَابُ.عذاب.اَلشِّدَّۃُ فِی الْحَرْبِ.گھمسان کی لڑائی.(اقرب)مزید تشریح کے لئے دیکھو سورۃ نحل ۸۲پس اُوْلِیْ بَأْسٍ کے معنے ہوں گے.جنگجو.جَاسُوا:جَاسُوْا جَاسَ(یَجُوْسُ جَوْسًا)اَلشَّیْءَ کے معنی ہیں.طَلَبَہٗ بِالْاِسْتِقْصَائِ.کسی چیز کو حاصل کرنے میں انتہائی محنت و کاوش سے کام لیا.اورجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّیَارِکے معنے ہیں.دَارُوْا فِیْھَابِالْعَیْثِ وَالْفَسَادِ.علاقوں میں فساد اورتباہی مچاتے ہوئے گھس گئے.وَفَسَّرَہُ الْجَوْھَرِی بِقَوْلِہٖ اَیْ تَخَلَّلُوْا فَطَلَبُوْا مَا فِیْہَا کَمَا یَـجُوْسُ الرَّجُلُ الْاَخْبَارَاَیْ یَطْلُبُہَا.اورجوہری نےجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ کے معنے یہ کئے ہیں وہ علاقوں میں گھس گئے.اورمال ودولت کوحاصل کرناچاہا.(اقرب) دیار.دِیَارٌ دَارَ کی جمع ہے.اور دَارٌ کے معنی اَلْمَحَلُُّّ.مکان.وَالْعَرْصَۃُ.صحن.میدان.اَلْبَلَدُ.شہر ملک.علاقہ (اقرب)خِلٰلَ الدِّيَارِ :مَاحَوَالِی حُدُوْدِھَا وَمَابَیْنَ بُیُوْتِہَا.ملکو ں کی حدوں اوران کے گھروں کے درمیان (اقرب) تفسیر.اب اس پیشگوئی کے پوراہونے کاحال بتاتاہے اورفرماتا ہے کہ جب پہلے وعدہ کا وقت آگیا تواے بنی اسرائیل ہم نے تم پر ایسے لوگ غالب کردئے جوسخت جنگ کرنے والے تھے.وہ آئے اور تمہارے گھرو ں میں گھس گھس کر انہوں نے تم کو ہلاک کردیا.وَکَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا.و ہ وعدہ ہما راپوراہوکررہنے والا تھا.یایہ کہ ہماراوعدہ پوراہوہی گیا ہے.آیت میں یہود پر دو عذابوں کا ذکر جن دوعذابوں کے متعلق اس آیت میں خبر دی گئی ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یوں کیا گیا ہے لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ(المائدۃ:۷۹) اس آیت سے معلوم ہوتاہے کہ ایک دفعہ حضرت دائود کے بعد عذاب آیا.اورایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے بعد آیا.یہود پر پہلے عذاب کا ذکر بائیبل میں پہلے عذاب کاحال بائبل سے یوں معلوم ہوتاہے کہ یہود حضرت موسیٰ کے بعد طاقتور ہوگئے تھے.حتی کہ حضرت دائود کے زمانہ میں ایک زبردست حکومت کی بنیاد پڑ گئی جو ان کے بعد بھی ایک عرصہ تک قائم رہی اورآخرآہستہ آہستہ کمزوری ہوتی گئی اورآخری زمانہ میں بابل کے شمال کے علاقہ میں بسنے والی اشوری قوموں نے ان کو شکست دی یہ قوم نینواکی بادشاہ تھی.انہوںنے یہود کواپنا باجگذار بنالیا
Page 299
اس کے بعد’’نیکو‘‘ایک مصر کاشہزادہ تھا.اس نے اسوریوں کو شکست دی اور وہ نینواکی بجائے مصریوں کے باجگذار بن گئے.۶۰۰سال قبل مسیح کے قریب اور حضرت دائود سے قریباً۴۰۰سال بعد یرمیاہ نبی کی معرفت ان کو ان کی خرابیوں پراللہ تعالیٰ نے پھر متنبہ کیا.اوران کے گناہو ںپر انہیں پھر تنبیہ کی اورفرمایاکہ اگر اب بھی توبہ کرلو توو ہ جو تمہارے لئے جلاوطنی کی پیشگوئی تھی ٹلادی جائے گی مگر وہ باز نہ آئے.(یرمیاہ باب ۷) آخراللہ تعالیٰ نے بابلیوں کوان کے عذاب کے لئے مسلّط کیا.یہ واقعہ بائبل کی کتا ب ۲سلاسطین باب۲۵میں یوں لکھا ہے ’’شاہِ بابل نبو کدنضر نے اوراس کی ساری فوج نے یروشلم پر چڑھائی کی.‘‘آیت ۱.اوراس کامحاصرہ کرلیا.یہ محاصرہ بہت دیر تک رہا.اس وقت یروشلم کابادشاہ صدقیاہ تھا.جب محاصرہ نے طول پکڑا توشہر کے اندر غلّہ کم ہوگیا لکھا ہے’’تب شہر ٹوٹا ‘‘آیت ۴یعنے بابل کی فوج نے فصیل توڑ دی.آخر لوگ ایک طرف کادروازہ کھول کر بھاگے صدقیاہ بادشا ہ بھی بھاگا مگر پکڑاگیاا س کی آنکھیں نکالی گئیں اورآنکھیں نکالنے سے پہلے اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے ہلاک کردیاگیا پھر اس کے پائوں میں بیڑیاں ڈال کر اسے بابل لے گئے آیت ۴تا۷.اس کے بعد شاہِ بابل نے اپنے ایک افسر بنوزردان کویروشلم بھجوایا.اس نے آکر ’’خداوند کاگھراوربادشاہ کا قصر (محل)اوریوروشلم کے سارے گھر ہاں ہرایک رئیس کاگھر جلادیا.اورکُسدیوں کے سار ے لشکر نے جو جلوداروں کے سردار کے ہمراہ تھا ان دیواروں کو جو یروشلم کے گرداگردتھیں گرادیا اورباقی لوگوں کوجو شہر میں چھو ڑے گئے تھے اوران کو جنہوں نے اپنوں کو چھو ڑکے شاہِ بابل کی پنا ہ لی تھی تمام جماعت کے بقیّہ کے ساتھ بنوزردان جلوداروں کا سردار پکڑ کر لے گیا‘‘آیت ۹تا۱۱.نحمیاہ نبی کی کتاب سے معلوم ہوتاہے کہ اس تباہی کاایک بڑاباعث سبت کی بے حرمتی تھی.چنانچہ لکھا ہے ’’تب میں نے یہودا ہ کے شریف لوگوں سے تکرار کرکے کہا کہ یہ کیا بُراکام ہے جوتم کرتے ہو کہ سبت کے دن کومقدس نہیں جانتے ہو کیاتمہارے با پ دادوں نے ایسانہیں کیااورہماراخداہم پر اوراس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تب بھی تم سبت کے دن کو پاک نہ مان کے اسرائیل پر زیادہ غضب بھڑکاتے ہو ؟‘‘باب ۱۳آیت ۱۷.۱۸.اسی طرح حزقیل نبی نے بھی ا س وقت یہود کوڈرایا تھا.انہوں نے ان کے بہت سے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے ان میں سے ایک گناہ یہ گنایا ہے کہ’’تُونے میرے مقدسوں کو ناچیز جاناہے اور میرے سبتوں کو ذلیل کیا ہے ‘‘ حزقیل باب ۲۲آیت۸.پھر باب ۲۳آیت ۳۸ میں ہے ’’اس کے سواانہوں نے مجھ سے یہ کیا ہے کہ اسی دن انہوں نے میرے مقدس کوناپاک کیا اور میرے سبتوں کو حرمت نہ دی ‘‘.
Page 300
میں نے سبت کی بے حرمتی کے حوالے اس لئے دئے ہیں کہ اس جگہ صرف سخت عذاب کی خبر بتائی گئی ہے مگردرحقیقت اشار ہ سورہ نحل کی آیات کی طرف ہے جن میں کہاگیا تھا کہ اِنَّمَاجُعِلَ السَّبْتُ عَلی الَّذِیْنَ اخْتَلَفُوْا فِیْہِ(النحل :۱۲۵)یعنی سبت کاعذاب ان لوگوں پر نازل کیاگیاتھاجنہوں نے الٰہی کلام میں اختلاف کرکے دین کو نقصان پہنچایاتھا.قرآن کریم کے مضامین کی ترتیب کی اس آیت میں ایک زبردست شہادت ہے کہ سورہ نحل جوبعد میںا ُتری ہے اس میں سبت کا ذکر ہے سورئہ بنی اسرائیل اس سے پہلے کی نازل شدہ ہے اوراس کے مضامین سورئہ نحل سے اس طرح چسپاں ہوجاتے ہیں گویاسورہ نحل پہلے کی ہے اوراِسراءبعد کی.اوراس میں سورہ نحل کے مضامین کے جواب دیئے گئے ہیں اوران کی تکمیل کی گئی ہے.تاریخ سے بابلیوں کی اس چڑھائی کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب یہود کمزور ہوگئے تواسوریوںنے فلسطین کو فتح کرکے اپنا تابع کرلیا.لیکن اس کے بعد ایک مصری بادشاہ فرعون نیکو (PHARAOH NECHO)نامی نے اسورین حکومت کو تباہ کردیا.اورفلسطین اسوریوں کی حکومت سے نکل کر مصر کی حکومت تلے آگیا.فرعون مصر نے یوسیاہ کے بیٹے الیاقیم (اس کانام یہویقیم کردیا گیا) ELIAKIM کو وہاں کابادشاہ بنادیا.لیکن اس دوران میں اسورین کی حکومت کی تباہی کودیکھ کر اس کے ہمسایہ کلدانی (CHALDEAN) بادشاہ نے اپنے بیٹے نبوکدنضر (NEBUCHADNEZZAR)کو نِیکو کے مقابلہ کے لئے بھیجا.اورنبوکدنضر نے مصر کو فتح کرلیا.اورفلسطین بابلیوں کے زیر اثر آگیا.مگر فلسطین کا بادشاہ یہویقیم مصر کی طرف مائل رہا.اس پر نبوکدنضرنے اس پر چڑھائی کی (یہ چڑھائی نبو کدنضر کے جرنیل نے کی ۵۸۷.ق.م.جس کانام بنوز رآدم تھا )مگراس کے لشکر پہنچنے سے پہلے بادشاہ یہویقیم مرگیا.اسکابیٹا یہویکین (JEHOICHIN ) تابِ مقابلہ نہ لاکر معافی کا طلبگارہوا.اسے بابل بلالیا گیا.اورصدقیاہ ( ZED CHIAH)(یہ یہویقیم کابھا ئی تھا اوراس کااصل نام متنیا ہ MATTANIAH تھا )کو فلسطین کابادشاہ بنادیا گیا.مگراس نے بھی مصر کے بادشاہ حوفرا ( HOPHRA ) کی طرفداری کی.اس پر بابلیوں نے ۵۸۸ قبل المسیح میں فلسطین کے دارالخلافہ کامحاصرہ کرلیا.آخر ۵۸۶قبل مسیح میں شہر کی دیوار توڑ دی گئی.صدقیاہ بھاگا.مگر گرفتارکرلیا گیا.اوربادشاہ کے حکم سے قید کرکے بابل پہنچایا گیا.بابلیوں نے یہود کی مقدس عمارات کو جلادیا.اورفصیل کو گرادیا.اورشہر برباد کر دیا.
Page 301
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ اَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ پھرہم نے تمہاری طر ف (دشمن پر )دوبارہ حملہ کی طاقت کولوٹادیا اورہم نے کئی قسم کے مالو ںاور(نیز)بیٹوں کے بَنِيْنَ وَ جَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا۰۰۷ ذریعہ سے تمہاری مدد کی.اورہم نے تمہیں جتھے کے لحاظ سے بھی(پہلے سے )زیادہ کردیا.حلّ لُغَات.اَلکَرَّۃ.کَرَّ الْفَارِسُ کَرًّاکے معنے ہیں فَرَّ لِلْجَوْلَانِ ثُمَّ عَادَ لِلْقِتَا لِ.شہسوار نے پہلے میدان جنگ میں چکر لگایا.پھر لڑنے کےلئے لوٹا.اَلْکَرَّۃُ کے معنے ہیں.اَلْمَرَّۃُ.باری.دفعہ.اَلْحَمْلَۃُ فِی الْحَرْبِ.لڑائی میں حملہ (اقرب)پس ثُمَّ رَدَدْنَالَکُمُ الْکَرَّۃَ کے معنے ہیں.تمہاری طرف دوبارہ حملہ کی طاقت کو لوٹادیا.نَفِیْرٌ.اَلنَّفِیْرُ لِمَادُوْنَ الْعَشَرَۃِ مِنَ الرِّجَالِ.دس سے کم لوگوں پر نَفِیْرٌ کالفظ بولتے ہیں.اَلْقَوْمُ یَنْفِرُوْنَ مَعَکَ وَیَتَنَافَرُوْنَ فِی الْقِتَالِ.وہ لوگ جو لڑائی کے لئے گھروں سے اکٹھے نکلیں.وَقِیْلَ ھُمُ الْجَمَاعَۃُ یَتَقَدَّمُوْنَ فِی الْاَمْرِ.اوربعض کہتے ہیں.کہ نفیر لوگو ں کی اس جماعت کو کہتے ہیں جو کسی کام میں پیش قدمی کرے.(اقرب) تفسیر.یعنی ا س تباہی کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے تم کو نجات دی اورطاقت عطا کی اور یہ اس طرح ہواکہ یہود کی اس تباہی کے بعد مید اورفارس کابادشاہ بابل پر چڑ ھ آیا اوربنی اسرائیل اپنے نبی کے حکم کے ماتحت اس کے ساتھ مل گئے اورا س نے ان کو قید سے آزاد کردیا.اس کاتفصیلی ذکر سورۃ بقرہ میںحضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں گذر چکاہے.یہود کی پہلی تباہی کے بعد نجات کی خبر بائیبل میں اس واقعہ کی نسبت حضر ت موسیٰ نے ان الفاظ میں پیشگوئی کی تھی ’’اوریو ں ہوگا کہ جب یہ سب کچھ تجھ پر گذرے گا.برکت اورلعنت جنہیں میں نے تیرے آگے رکھا اورتوان سب گروہو ں میں جہاں جہاں خداوند تیراخدا تجھ کو بھگائے انہیں یاد کرے گااورتو خداوند اپنے خدا کی طر ف پھر ے گا.اوران حکمو ں کے موافق جو آج میں نے تجھے کہے تُواپنے بال بچوںسمیت اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی سے اس کی آواز کوسن لے گا.تب خداوند تیراخدا تیری اسیری کو بدلے گا.اورتجھ پر رحم کرے گا.
Page 302
اورپھرکے تجھ کو ان سب گروہوںمیں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھے تتّربتّرکیاتھا تجھے جمع کرے گا.اگر تجھ میں سے کوئی آسمان کی اس انتہاتک بھگایاگیاہوگا تو خداوند تیر اخدا وہاں سے تجھے جمع کرے گااوروہاںسے تجھے پھیر لائے گا.اورخداوند تیراخداتجھ کواس زمین جس پر تیرے باپ دادے قابض ہوئے لائےگااورتُواس کامالک ہوگا.اوروہ تجھ سے نیکی کرے گااورتیرے باپ دادوں سے زیادہ تجھے بڑھائے گا‘‘استثنا باب۳۰آیت ۱تا۵.ان آیات سے معلو م ہوتاہے کہ حضرت موسیٰ ؑ نے پہلی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی دوبار ہ بحالی کی خبر دی تھی اوراسی کی طرف ان آیا ت میں اشارہ ہے اوراس بحالی کاحال یہ ہے کہ ۴۴۵قبل مسیح میداورفارس کے بادشاہ نے جس نے بابل فتح کرلیا تھا.ا س صلہ میں کہ یہود نے اس کی مدد کی تھی ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دےدی.یہود کے ایک نبی نحمیاہ کودوبار ہ آبادکرنے کے لئے بھیجا گیا تاوہ یروشلم اور دوسرے یہودی مقامات کو دوبار ہ آباد کریں اس بادشاہ کانام خورس تھا اورانگریزی میں اسے سائرس لکھتے ہیں.اس نے نہ صرف یہود کو ان کے وطن میںواپس جانے کی اجازت دی بلکہ وہ سامان جو وہاں سے نبوکدنضرلے گیاتھا وہ بھی ان کوواپس دےدیا.(عزراباب۱ آیت ۲،۳،۷ ، ۸) (یہ عزراوہی عزیر ہیں جن کا قر آن کریم میں ذکر آتاہے کہ یہود انہیں خدا کا بیٹاکہتے تھے ) اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ١۫ وَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا١ؕ (اب)اگرتم نیوکاربنو گے تونیکو کا ربن کر اپنی جانوں کو ہی فائدہ پہنچائوگے اوراگر تم براکروگے فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا تو(بھی)ان(ہی)کےلئے( براکروگے)پھر جب دوسری بار والا وعدہ (پوراہونے کا وقت )آگیا.تاکہ وہ (یعنے الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ لِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تمہارے دشمن)تمہارے معزز لوگوں سے ناپسندیدہ معاملہ کریں اور(اسی طرح )مسجد میں داخل ہو ں.جس طرح تَتْبِيْرًا۰۰۸ وہ اس میں پہلی بار داخل ہوئے تھے.اورجس چیز پر غلبہ پائیںاسے بالکل تباہ(وبرباد )کردیں.حلّ لُغَات.لِیَسُوْءٗ:لِیَسُوْءٗ سَاءَ سے مضار ع مذکر غائب کا صیغہ ہے.اورسَاءَ ہٗ(یَسُوْءُ ہٗ سَوْءً ا)
Page 303
کے معنے ہیں.فَعَلَ بِہِ مَایَکْرَھَہُ اَوْاَحْزَنَہٗ.اس سے ایسا معاملہ کیا جس کو وہ ناپسند کرتا تھا یااس کوغمگین کیا (اقرب) وُجُوہٌ:وُجُوہٌ وَجْہٌ کی جمع ہے.اوراَلْوَجْہُ کے معنے ہیں نَفْسُ الشَّیْءِ.کسی چیز کی ذات.سَیِّدُالْقَوْمِ.قو م کاسردار.اَلْجَاہُ.عزت.(اقرب) وَلِیُتَبِّرُوْا:وَلِیُتَبِّرُوْاتَبَّرَ سے مضارع مذکر غائب کاصیغہ ہے اورتَبّرَہٗ کے معنے ہیں.اَھْلَکَہُ وَدَمَّرَہُ.اس کو ہلاک و تباہ کردیا.تَبَّرَ کُلَّ شَیْءٍ.کَسَّرَہُ وَفَتَّتَہُ.کسی چیز کو توڑ کر ٹکڑ ے ٹکڑ ے کردیا.اَلتَّبَارُ.اَلْھَلَاکُ.ہلاکت (اقرب)وَلِیُتَبِّرُوْ ا کے معنے ہوں گے.کہ وہ ہلا ک کردیں.تفسیر.یہود کا دوسرا فساد اور اس کی سزا اس آیت میں یہود کے دوسرے فساد کی خبر دی گئی ہے اورپھر اس کی سزاکا ذکر کیا گیا ہے.فساد ان کاحضرت عیسیٰ کو دکھ دیناتھا.اورسزاان کا رومیو ں کے ہاتھو ں سے تباہ ہونا تھا.یہ واقعہ ۷۰ء بعد مسیح کا ہے.گویا حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہی یہ واقعہ ہو ا.کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتاہے کہ ان کی عمر ۱۲۰سال تھی.اورتینتیس سال کی عمر میں و ہ صلیب پر لٹکائے گئے تھے (قاموس الکتاب زیر لفظ عہدنامہ کا تواریخی خاکہ).اس عذاب کی تفصیل یہ ہے کہ وسیپین نامی ایک رومی جرنیل تھا اسے بادشاہ روم نے یہود کی سرکشیوں کی و جہ سے ان کی سر کوبی کاحکم دیاتھا.جب یہ اس حکم کے بجالانے میں مشغو ل تھا.اسے ایک کشف نظر آیا جس کی تعبیر اس نے یہ کی کہ مجھے روم واپس جانا چاہیے.کیونکہ وہاں سے فسادات کی خبریں آرہی تھیں.اس کے واپس لوٹنے پر وہاںکچھ ایسے حالات پیداہوئے کہ اسے بادشاہ بنادیاگیا.اوراس نے اپنے بیٹے ٹائٹس کو فلسطینی مہم کاافسر مقررکر دیا.جس نے یروشلم کو ۷۰ ء بعد مسیح فتح کرکے اس کے گرائے جانے کاحکم دیا.اورشہر کی دیواروں اورمسجد کو گرادیاگیا اوریہودی حکومت کاخاتمہ ہوگیا.گو ۱۳۵ ء میں یہود نے پھر ایک ناکا م بغاوت کی مگر وہ صرف چراغ سحری کے آخر ی شعلہ کی سی حیثیت رکھتی تھی.(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ JEWاورہسٹورئینزہسٹری آف دی ورلڈ) بائبل میں یہود کی دوسری تباہی کا ذکر اس واقعہ کی نسبت بائبل میں ان الفاظ میں حضرت موسیٰ کی پیشگوئی درج ہے.’’انہوں نے اجنبی معبودوں کے سبب اسے غیر ت دلائی اوروہ اسے نفرتی کاموں سے غصے میں لائے.انہوں نے شیطانوںکے لئے قربانیاں گذرانیںنہ خداکے لئے.بلکہ ایسے معبودوں کے لئے جن کو آگے وے نہ پہچانتے تھے.جو نئے تھے اورحال میں معلوم ہوئے اوران سے تیرے باپ دادے نہ ڈرتے تھے.تواس چٹان
Page 304
سے جس نے تجھے پیدا کیا غافل ہوا.اوراس خدا کو جس نے تجھی صورت بخشی بھول گیا.اورجب خداوند نے یہ دیکھا توان سے نفرت کی اس لئے کہ اس کے بیٹوں اوراس کی بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا.اوراس نے یہ فرمایا کہ میں ان سے اپنامنہ چھپائوں گا.تاکہ میں دیکھو ںکہ انجام کیا ہوگا اس لئے کہ وہ کج نسل ہیں.ایسے لڑکے جن میں امانت نہیں انہوں نے اس کے سبب سے جو خدا نے مجھے غیرت دلائی اوراپنی واہیات باتوں سے مجھے غصہ دلایا.سو میں بھی انہیں اس سے جو گرو ہ نہیں غیرت میں ڈالوں گااورایک بے عقل قوم سے انہیں خفاکروں گا کیونکہ میرے غصے سے ایک آگ بھڑکی ہے جو اسفل جہنم تک جلے گی او رزمین کو اس کے پیداوار سمیت کھاجائے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں کو جلا دے گی.میںا ن کی بلائوں کو ان کے اوپر بڑھائوں گا اوران پر اپنے تیروں کو خرچ کروں گا.وہ بھوک سے جل جائیںگے.اورسوزندہ گرمی اورکڑوی ہلاکت کے لقمے ہو ں گے.میں ان پردرندوں کے دانتوں اورزمین کے زہر دار سانپوں کو چھوڑوں گا.باہر سے تلوار اوراندر کے مکانوں سے خوف جوان کو اورکنواری کو بھی.شیرخوار کو اور سرسفید کوبھی ہلاک کریںگے‘‘.استثنا ء باب ۳۲آیت ۱۶تا۲۵.یہ پیشگوئی پہلی پیشگوئی کے بعد بلکہ اس پیشگوئی کے بھی بعد کہ پہلے فساد کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کوواپس یروشلم میں لے آئے گا.بیان ہوئی ہے جس سے ظاہر ہے کہ اس سے پہلے عذاب کے بعد ایک دوسرے عذاب کی خبر دی گئی ہے.اوریہ عذاب وہ دوسراعذاب ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے لَتُفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ کے الفاظ میں کیا ہے.عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ١ۚ وَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا١ۘ وَ (اب بھی )کچھ بعید نہیں کہ تمہارارب تم پر رحم کردے اوراگر تم (پھراپنے اسی رویہ کی طرف)لوٹے توہم بھی (اپنی جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا۰۰۹ اسی سنت کی طرف) لوٹیں گے اور(یاد رکھو کہ)جہنم کو ہم نے کافروں کے لئے قید خانہ بنایا ہے.حل لغات.الحَصِیْرُ.السِّجْنُ.قید خانہ (اقرب) تفسیر.بنی اسرائیل کے لئے کامل تباہی کے بعد ترقی کی امید قرآن کریم کے ذریعہ بنی اسرائیل کی کامل تباہی کی خبردینے کے بعد اب قرآ ن کریم انہیںامید کاپہلو دکھاتا ہے اورفرماتا ہے کہ بائبل
Page 305
کاجہاں تک تعلق ہے تم ہمیشہ کے لئے ہلاک کردئے گئے ہو مگرموسوی مذہب سے باہرہوکر تمہاری ترقی کی راہ ابھی کھلی ہے اوروہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعہ سے دوبارہ ترقی کرنے کا تمہاری قوم کو موقعہ دیا ہے اس موقعہ سے فائدہ اٹھائو اوراللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہوجائو.لیکن اگر تم نے اس موقعہ سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تواللہ تعالیٰ کی سزائیں دوبار ہ تم کو آگھیریں گی اور تم بالکل تباہ ہوجائو گے.دیکھو ان آیات میں یہودی قوم کو سمجھانے کے لئے کیسااحسن طریق اختیار کیا ہے خود ان کی کتب سے ان کی تباہی کی خبر دی ہے اوربتایا ہے کہ خود یہودی کتب کے مطابق اب کوئی مستقبل یہودیت کے لئے باقی نہیں.پس جب خود ان کی کتب ان کی ہلاکت کافتویٰ دے چکی ہیں توان کو اس متروک راستہ کو چھوڑنے میں جسے خدا تعالیٰ چھڑواچکا ہے عذرنہیں ہوناچاہیے اوراسلام کو قبول کرکے دینی ودنیو ی انعامات حاصل کرنے چاہئیں.اس نئے راستہ کے متعلق بھی بائبل میں خبر موجود ہے.آنحضرت ؐ کے متعلق پیشگوئی بائیبل میں استثناء باب ۳۳آیت ۱تا ۳میں فرماتا ہے ’’اوریہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مردِ خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی اور اس نے کہا کہ خداوند سیناسے آیا اورشعیرسے ان پر طلوع ہوا.فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا.دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اوراس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لئے تھی.ہاں و ہ اس قوم سے بڑی محبت رکھتا ہے.ا س کے سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اوروہ تیرے قدموں کے نزدیک نزدیک بیٹھے ہیں اورتیر ی باتوں کو مانیں گے ‘‘.یعنی اللہ تعالیٰ فاران سے جلوہ گر ہونے والے نبی کے ذریعہ سے پھریہود کی برکت کاسامان پیداکرے گا.اگر وہ چاہیں توہدایت پاکر ترقی کرسکتے ہیں.یہ پیشگوئی تباہی کی خبر کے معاً بعد دوسرے باب میں بیان ہوئی ہے.مسلمانوں پر دو دفعہ تباہی آنے کی پیشگوئی یادرکھنا چاہیے کہ آیات مذکورہ بالاجہاں یہ بتارہی ہیںکہ یہود کامستقبل خود ان کی کتب کے رُو سے بالکل تاریک ہے وہاں مسلمانوں کوبھی توجہ دلائی ہے کہ مسلمانوں پر بھی اسی طرح دوبارہ ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے عذاب آئے گا.مسلمانوں پر پہلی تباہی یعنی بنو عباس پر خطرناک تباہی کے دن چنانچہ پہلا عذاب خلافت عباسیہ کے خاتمہ پرآیا.اس کاموجب بھی وہی تھا جوبائبل نے یہود کی تباہی کاموجب بتایا ہے.یعنے فرغانہ کی فتح کے بعدمسلمانوں نے کثرت سے وہاں کی خوبصورت لڑکیوں سے شادیاں کرلیں.یہ علاقہ بہت مشرک تھا.ان عورتوں کے اثر سے مسلمانوں میں بھی مشرکانہ عقائد پیدا ہونے لگے.اوراسلامی غیرت کمزورہونے لگ گئی.آخر ایک وحشی
Page 306
قوم نے بغداد پر حملہ کردیا جواپنی وحشت اوراجنبیت کے لحاظ سے اسلامی ممالک اوران کی تہذیب سے ویسی ہی بیگانہ تھی جیسی کہ بابل کی قوم جس نے فلسطین پر حملہ کیاتھا اٹھارہ لاکھ مسلمان صر ف بغداد اوراس کے گردونواح میں قتل کیاگیا (الخلافۃ العباسیۃ لِعبد الفتاح السر نجاوی صفحہ ۲۹۶،۲۹۷).شاہی خاندان کے تما م لوگوںکو ان کی فہرستیں بنوابنواکر اورتلاش کرکرکے قتل کیا گیا.کہتے ہیں کہ صرف ایک شخص بھاگ کر بچ سکااوراسی کی نسل سے بہاولپور کے والیانِ ریاست ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی خاندان ایسانہیں جواپنے آپ کو عباس کی طرف منسوب کر ے (اس نوٹ لکھنے کے بعدمجھے معلوم ہواہے کہ یوپی میں عباسی خاندان کی بعض شاخیں موجود ہیں ان میں سے ایک نے مجھے اپنا شجرہ نسب بھی بھجوایاہے ).مسلمانوں پر دوسری تباہی دوسری تباہی آخری زمانہ کے وقت مقدر تھی جس کے آثار اب نمودارہورہے ہیں.عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ١ۚ وَ اِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا١ۘ وَ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا.العیاذ باللہ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ یہ قرآ ن یقیناً اس (راہ کی)طرف رہنمائی کرتاہے جوسب سے زیاد ہ درست ہے اورمومنوں کو جومناسب حال کام الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًاۙ۰۰۱۰ کرتے ہیں بشارت دیتاہے کہ ان کے لئے (بہت )بڑااجر(مقدر)ہے.تفسیر.مسلمانوں کے لئے ڈرنے کا مقام یہ قرآن کریم یقیناًا س مقصد کی طرف ہدایت کرتا ہے جوپہلے لوگوں کے مقاصد سے بہت اعلیٰ ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کے نتائج بھی ان کتابوں سے اعلیٰ ہی نکلیں اوروہ انعام جو اس کے نتیجہ میں ملیں گے و ہ روحانی بھی ہوں گے اور جسمانی بھی.پس اس پر عمل کرو.اورانعام حاصل کرو.اسی طرح اس میں مسلمانوں سے کہاگیاہے کہ تم کو پہلے لوگوں سے بڑھ کر اوربہترانعام ملنے والا ہے.پس تم کو ان لوگوں سے زیادہ ہوشیار رہناچاہیے تاایسا نہ ہو کہ کسی وقت تمہاری نسلیں انعام پر اتراکر خراب ہوجائیں اور الٰہی عذاب کی مستحق ہوجائیں.
Page 307
وَّ اَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اوریہ کہ جو لوگ آخر ت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے ہم نے دردناک عذاب اَلِيْمًاؒ۰۰۱۱ تیار کیا ہے.تفسیر.اس آیت میں اس مضمون کی طرف جوپہلی آیت میں اشارہ بیان ہواتھا واضح کیاگیا ہے اورفرماتا ہے کہ جوقوم بھی اپنے انجام سے غافل ہوجائے آخر عذاب میں مبتلاہوجاتی ہے.آخرت کے معنی آخرت کے معنے بعد میں آنے والی چیز کے ہوتے ہیںقرآن کریم میں چونکہ یوم آخرت کا بار بار ذکر ہے لوگوں کے ذہن پر یہ امر مسلط ہوگیاہے کہ آخر ت کے معنے صرف یوم آخر ۃ کے ہیں.حالانکہ یہ درست نہیں.آخرت کے اصل معنے بعد میں آنے والی شئے کے ہیں.پس جس موقعہ پراس لفظ کااستعمال ہواسی کے مطابق اس کے معنے کئے جانے چاہئیں.اس جگہ موقعہ کے لحاظ سے قوموں کے انجام کے معنے نہایت مناسب ہیں اور معنے یہ ہیں کہ جوقومیں اس امر کوبھلادیتی ہیں کہ ہرکمالے رازوالے.اوراپنے انجام کی اصلاح سے غافل ہوجاتی ہیں.وہ اپنی ذمہ واریوں کی ادائیگی میں بھی سست ہوجاتی ہیں اوراللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہوجاتی ہیں پس ہرقوم کو اپنے انجام کو زیرنظررکھناچاہیے اورہرخرابی کے موقعہ پر اپنی قو م کی اصلاح کرلینی چاہیے تاکہ اسے نئی زندگی ملتی رہے اورخدا تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ جائے.اس آیت سے پہلے جو واؤ عاطفہ ہے وہ انہی معنوں پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس سے معلو م ہوتاہے کہ یہ حکم مسلمانوں کو ہے اورمسلمان یو مِ آخر پرایما ن رکھتے تھے اس کے منکرنہ تھے.
Page 308
وَ يَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ١ؕ وَ كَانَ اورجس طرح انسان ؎۱ بھلائی کو اپنی طرف بلاتا ہے اسی طرح وہ برائی کو بھی اپنی طرف بلاتاہے اورانسان بڑا الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا۰۰۱۲ جلد باز (واقع ہوا)ہے.؎۱ قرآنی الفاظ میں انسان کالفظ برائی کو پکارنے کے ساتھ استعما ل ہواہے او روہ کی ضمیر بھلائی کو پکارنے کے فقرہ میں استعمال ہوئی ہے لیکن اردومیں چونکہ بھلائی کا ذکر پہلے ہے اوربرائی کابعد میں کرنا پڑا.اس لئے انسان کالفظ مجبوراً بھلائی کے ساتھ اوروہ کی ضمیر برائی کے ساتھ لگانی پڑی.حلّ لُغَات.یَدْعُ الانسانُ.یَدْعُوْدَعَاسے مضارع واحد مذکر غائب کاصیغہ ہے اوردَعَاہُ (یَدْعُوْ دُعَاءً وَدَعْوًا) کے معنے ہیں.رَغِبَ اِلَیْہ.اس کی طرف متوجہ ہوا.دَعَازَیْدًا: اِسْتَعَانَہُ.زید سے مدد طلب کی.دَعَافُلَانًا:نَادَاہُ وَصَاحَ بِہِ.اس کوپکارا.دَعَاہُ اِلَی الْاَمْرِ :سَاقَہُ اِلَیْہِ.کسی کام کی طرف اسےلے گیا.دَعَافُلَانًا(دَعْوَۃً وَمَدْعَاۃً)طَلَبَہُ لِیَاْکُلَ عِنْدَہُ.اسے کھانے کی دعوت دی (اقرب) دَعَابِہِ : اِسْتَحْضَرَہُ اسے آنے کی دعوت دی (المنجد)کُلُّ شَیْءٍ فِی الْاَرْضِ اِذَا اِحْتَاجَ اِلٰی شَیْءٍ فَقَدْ دَعَابِہ لِمَنْ اَخْلَقَتْ ثِیَابُہُ قَدْ دَعَتْ ثِیَابُکَ اَیْ اِحْتَجْتَ اِلَی اَنْ تَلْبَسَ غَیْرَھَا.جب کسی طرح کسی چیز کی احتیاج دوسری چیز کی طرف معلوم ہو تواس احتیاج کو ظاہرکرنے کےلئے بھی دعا کافعل باء کے صلہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں.چنانچہ کسی پرانے کپڑوں والے کو جب دَعَتْ ثَیَابُکَ کہیں تواس کے معنے یہ ہوں گے کہ اس کے کپڑے اس بات کی ضرورت کوظاہر کرتے ہیں کہ ان کواتار کر ان کی جگہ اورکپڑے تبدیل کئے جائیں دَعَابِالْکِتَابِ کے معنے ہیں.اِسْتَحْضَرَہُ.کہ کسی کتا ب کو حاصل کرنے کی خواہش کی (تاج) اَلْخَیْرُ اَلْخَیْرُکے معنوں کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۱۲ نحل آیت نمبر ۳۱.اَلْعَجُوْلُ: اَلْعَجُوْلُ عَـجَلَ سے مبالغہ کاصیغہ ہے اوراَلْعَجُوْلُ کے معنی ہیں.اَلْمُسْرِعُ.جلدی کرنے والا.اَلْکَثِیْرُ الْعُجْلَۃِ.جلدباز (اقرب) تفسیر.یہ آیت ان معنوں کی تصدیق کرتی ہے جومیں نے اوپر کی آیت کے کئے ہیں.کیونکہ اس میں
Page 309
اسی مضمو ن کی تشریح کی گئی ہے قیامت کا ذکر نہیں کیاگیا.بلکہ اگلی آیتوں میں بھی وہی مضمون بیان ہواہے.یَدْعُ الْاِنْسَانُ کا مطلب اور دَعَا ہُ کے مختلف معنی اس سے پہلے کہ میں ا س آیت کامفہوم بتائوں.میںاس آیت کاترجمہ سمجھادیتاہوں.دَعَاہُ کے معنے اسے پکارنے اس کی طرف توجہ کرنے اوراس سے مدد مانگنے کے ہوتے ہیں لیکن دَعَابِہِ کے معنے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دینے کے ہوتے ہیں.پس اس آیت کامفہوم یہ نکلتاہے کہ جبکہ انسان ظاہری طور پر خیر کوبلارہاہوتاہے وہ حقیقت میں شرکوبلارہاہوتاہے یایہ نکلتاہے کہ خیر کو بلانے کاجو حق ہے اس کی مانند و ہ شرکو بلاتا ہے.قوموں کو ترقی دینے سے اللہ تعالیٰ کی غرض ان دونوں معنوں کے روسے آیت کامطلب یہ ہے کہ جب قوموں کوترقی ملتی ہے و ہ اس امر کو بھول جاتی ہیں کہ یہ ترقی انہیں اس لئے ملی ہے کہ تاوہ دین و دیانت کو قائم کریں اوربنی نوع انسان کے لئے امن اورترقی کے سامان پیداکرکے خداکے فضلوں کو حاصل کریں.اور وہ دنیاوی نعمتوںکوجمع کرنے میں مشغول ہوجاتی ہیں.اورلوگوں کے حقوق کو نظرانداز کردیتی ہیں.اوردنیوی عیش و آرام کے سامان جمع کرکے یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اپنے لئے اوراپنی اولادوں کے لئے خیر کے سامان جمع کررہی ہیں.حالانکہ حقیقت میں وہ اس ذمہ واری کوبھول کرجوان کے کندھوں پررکھی جاتی ہے اپنی تباہی کے سامان پیداکررہی ہوتی ہیں اورآخر تباہ ہوجاتی ہیں.قوم کی ترقی کا وقت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے پس کسی قوم کوترقی ملنے کا وقت اس کے لئے بہت نازک ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد اصل خیر اس کی نظرسے پوشیدہ ہوجاتی ہے اورشرّکو خیرسمجھ کر وہ اپنے راستہ سے بھٹک جاتی ہے.وَ كَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا کہہ کر اس طرف اشار ہ کیاہے کہ مومن کو جو خیر ملتی ہے وہ تومرنے کے بعد ملتی ہے.اس دنیا کی فتوحات اس خیر کے حصہ کے لئے مواقع بہم پہنچانے کے لئے د ی جا تی ہیں لیکن بعض لوگ جلدی کرتے ہیں اوراس دنیا کی ترقی کو اصل خیر سمجھ کر اس کے سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں.اورخود اپنے اعمال سے اپنی تباہی کے سامان جمع کرلیتے ہیں.غرض ا س آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر کسی قوم کو ترقی ملے مثلاًحکومت ملے.جاہ وثروت ملے تواسے ایسے کام کرنے چاہئیں کہ وہ نعمت قائم رہے.اوراس کے ذریعہ سے اُخروی خیر کاذخیر ہ جمع ہوتا رہے.نہ کہ ایسے کام جس سے و ہ جلدی زائل ہوجائے اوراُخروی انعامات کے حصول کے مواقع ہاتھ سے نکل جائیں.دُعَائَ ہٗ بِالْخَیْرِ کے ایک معنی تواوپر بتائے گئے ہیں.دوسرے معنے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ انسان شرّکو اسی طرح بلاتاہے جس
Page 310
طرح وہ خیر کو بلارہاہوتاہے.یعنی انسان بھی عجیب ہے کہ منہ سے توخیر مانگ رہاہوتاہے.یعنی خواہش تویہی رکھتاہے کہ اسے ہرقسم کی خیر مل جائے.مگرعمل کے لحاظ سے وہ شرّکوبلارہاہوتاہے.گویا اپنی نادانی سے ایک ہی وقت میں دومتضاد باتیں طلب کرتاہے منہ سے خیر اورعمل سے شر.ان معنوں کے روسے اس آیت کامطلب یہ ہوگاکہ اصل کامیابی تب ہوتی ہے جب انسان کادل اوراس کاعمل متفق ہوں.یعنی اگردل سے خیر مانگتاہے تواعمال سے بھی خیر ہی مانگے.(۳)تیسری صورت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ ہٗ کی ضمیر کو انسان کی طرف پھیراجائے.اوراسے مفعول کی ضمیر قرار دیاجائے.اوردعا کافاعل خدا تعالیٰ کوقرار دیاجائے.اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ انسان شرکواسی جوش سے بلاتا ہے جس جوش سے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی بندہ کو خیر کی طرف بلارہاہوتاہے.یعنی ہم توکہتے ہیں کہ اے انسان تُو بھلائی کی طرف آ.مگر وہ کہتاہے اے بلاتُو میر ی طرف آ.ان معنوں کے روسے اس آیت کایہ مطلب ہوگاکہ ہم توانسانوں کے لئے خیر کے سامان مہیاکررہے ہیں.مگر ان میں سے بعض اپنے اعمال سے شرکو بلانے میں لگے ہوئے ہیں اوراپنی تباہی کاساما ن پیداکررہے ہیں.عَجُوْلًا کے لفظ میں اس حقیقت کو ظاہر کیاکہ انسان غوروفکر سے کام نہیں لیتا.اگروہ غوراورفکر سے کام لے توضرور اسے معلوم ہوجائے کہ میں غلطی کررہاہوں.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے والا انسان اگرذراٹھہر جائے تواس کاغصہ ضرور کم ہوجائے.اوراسے سوچنے کاموقعہ ملے.(مسند احمد مسند ابو ذر غفاری) تمام بدیوں کی وجہ جلد بازی ہوتی ہے تمام بدیوں کی وجہ جلد بازی ہی ہوتی ہے.اگرایک انسان بدی کے وقت ذراتأنّی سے کام لے اورپہلے سوچ لے کہ یہ کام میرے لئے مفیدہے یامضر.تویقیناًوہ اس بدی سے بچ جائے.وَ جَعَلْنَا الَّيْلَ وَ النَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَاۤ اٰيَةَ الَّيْلِ وَ جَعَلْنَاۤ اورہم نے رات اوردن (کے)دونشان بنائے ہیں اس طرح پر کہ رات والے نشان کے اثر کوتوہم نے مٹادیا اور اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوْا دن والے نشان کو ہم نے بینائی بخشنے والابنادیا.تاکہ تم (آسانی سے )سالوں کی گنتی اورحساب معلوم کرسکو اورہم
Page 311
عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ١ؕ وَ كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا۰۰۱۳ نے ہرایک چیز کو خوب کھول کربیان کردیاہے.حلّ لُغَات.مُبْصِرَۃٌ مُبْصِرَۃٌ اَبْصَرَسے اسم فاعل مؤنث کاصیغہ ہے اوراَبْصَرَہُ (متعدی)کے معنے ہیں جَعَلَہٗ بَصِیْرًا.اس کو دیکھنے والابنادیا(یعنے دکھایا)اَبْصَرہٗ :رَاہُ.اس کودیکھا.اَخْبَرَہُ بِمَاوَقَعَتْ عَیْنُہُ عَلَیْہِ.اس کو وہ بات بتائی جس پر اس کی نظرپڑی تھی.اَبْصَرَ الطَّرِیْقُ(لازم)اِسْتَبَانَ وَوَضَحَ.راستہ واضح ہوگیا.(اقرب)پس مُبْصِرَۃً کے معنے ہوئے بینائی بخشنے والی.مَـحَوْنَا:مَـحَوْنَا مَحٰی سے جمع متکلم کاصیغہ ہے اورمَـحَاالشَّیْءَ (یَمْحُوْ)کے معنے ہیں.اَزَالَہٗ وَاَذْھَبَ اَثَرَہُ.کسی چیز کو مٹادیا اوراس کے اثر کودورکردیا (اقرب) وَالْمَحْوُ: اَلسَّوَادُ فِی الْقَمَرِ.اورمحوچاند کے بے نور حصہ کو بھی کہتے ہیں (تاج )پس مَـحَوْنَااٰیَۃَ اللّیْلِ کے معنے ہوں گے کہ رات والے نشان کو ہم نے مٹادیا (۲)بے نورکردیا.فَضْلًا: اَلفَضْلُ(فَضَلَ الشَّیْءُ یَفْضُلُ)کامصدرہے.اوراس کے معنے ہیں.ضِدُّالنَّقْصِ.خوبی.فضیلت.اَلْبَقِیَّۃُ.بقیہ (حاصل تفریق کوبھی انہی معنوں میں فضل کہتے ہیں )اَلزِّیَادَۃُ.زیادتی.اَ لْاِحْسَانُ.احسان.وَالْفَضْلُ فِی الْخَیْرِوَ یُسْتَعْمَلُ لِمُطْلَقِ النَّفْعِ.نفع(اقرب) العدد:اَلْعَدَدُ اِسْمٌ مِنْ عَدَّبِمَعْنَی الْاِحْصَاءِ یہ عدّکااسم ہے.اوراس کے معنے ہیں.شمار.گنتی.الْمَعْدُوْدُ.شمار کیاہوا.اس کی جمع اعداد آتی ہے (اقرب)پس لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ کے معنے ہوں گے کہ تم سالوں کی گنتی کو معلوم کرسکو.تفسیر.فَمَحَوْنَاۤ اٰيَةَ الَّيْلِ میں فاء تعقیب کی نہیں.یعنی یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ نے پہلے رات اوردن بنائے پھران میں سے ایک کو مٹادیا.بلکہ یہ فاء تفسیر ی ہے.اورمطلب یہ ہے کہ ہم نے رات اوردن کو اس صورت میں بنایاہے کہ رات تو ایک مٹاہوانشان ہے.اوردن ایک روشن نشان ہے.یعنی رات سے مخفی فائدہ پہنچتاہے اوردن سے ظاہر.اوریہ دونوں اپنی اپنی جگہ نفع بخش ہیں.چنانچہ دونوں کے ذریعہ تم نفع حاصل کرتے ہو.اور تاریخوں کاعلم ان کے ذریعہ سے حاصل کرتے ہو.نیزحساب کافائدہ بھی حاصل کرتے ہو.تاریخ کافائدہ توظاہر ہی ہے.حسا ب کاعلم اس طرح کہ لمبی تاریخ کویاد رکھنے سے ہی حساب پیدا ہوتا ہے.نیز اس طرح کہ سال کا وقت تجویز کرنے کاتعلق چاند اورسورج سے ہے اورصحیح جنتری سو رج کی رفتار کے علم کے بغیر نہیں بن سکتی.
Page 312
سورج اور چاند کی گردش کا تعلق حساب سے اسی طرح سورج اورچاند کی گردش کاتعلق بھی حساب سے ہے.اس پر غور کرتے ہوئے انسان کو باریک در باریک حساب سے واسطہ پڑتا ہے.چنانچہ آج تک شمسی حساب کوانسان مکمل نہیں کرسکا.اورشمسی سال کی تعیین میں غلطیاں کرتاچلاآیاہے جسے علم حساب کی ترقی کے ساتھ ساتھ دورکیاجارہا ہے.رات کی تاریکی اور دن کی روشنی انسان کی جسمانی ترقی کا ذریعہ ہیں اس آیت میں یہ بتلایاگیاہے کہ نشان دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک ترقی کا نشان ہوتاہے.اورایک مٹنے کا نشان ہے.پس تم ایسے نشان طلب کرو جن کے ذریعہ سے ترقی ہو.ایسانشان نہ مانگو جس سے تم مٹ جائو.اورترقی اورتنزل دونوں حالتوں کو روحانی کمالات کے حصو ل کاذریعہ بنائو.جس طرح رات جو تاریکی کا نشان ہے.اوردن جوروشنی کا نشان ہے.دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جسمانی ترقی کاذریعہ بنادیا ہے نہ تکلیف کے وقتوں میں خدا کوبھولو نہ کامیابی کے وقتوں میں اس کو چھوڑو.وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓىِٕرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ١ؕ وَ نُخْرِجُ لَهٗ اور(ہم نےذمہ وار بنایا ہے )ہرانسان کو (اس طرح کہ )ہم نے اس کی گردن میں اس کے عمل کوباندھ دیا ہے يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا۰۰۱۴ اورہمقیامت کے دن اس (کے اعمال )کی ایک کتاب نکال کراس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ (بالکل)کھلی ہوئی پائےگا.حلّ لُغَات.اَلْزَمْنٰہُ اَلْزَمْنٰہُ اَلْزَمَ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے.اوراَلْزَمَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں.اَثْبَتَہُ وَاَدَامَہُ.کسی چیز کو ہمیشہ رکھا.اَلْزَمَ فُلَانًا الْمَالَ والعَمَلَ اَوْجَبَہ عَلَیْہ.اس پر کسی کام کو کرنا یاکسی مال کو اداکرنا واجب کردیا.(اقرب) طَائِرٌ اَلطَّائِرُ کُلُّ ذِیْ جَنَاحٍ مِنَ الْـحَیَوَانِ.پرندہ.نیز اس کے معنے ہیں.اَلْحَظُّ.نصیب.رِزْقُ الْاِنْسَانِ.انسان کی روزی.عَمَلُہُ الَّذِی قُلِّدَ ہُ وَطَارَعَنْہُ مِنْ خَیْرٍ اَوْشَرٍّ.انسانی اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے.کہتے ہیں ھُوَمَیْمُوْنُ الطَّائرِ:اَیْ مُبارَکُ الطَّلْعَۃِ.وہ مبارک چہرے والا ہے.نیز مسافر کو رخصت
Page 313
کرتے وقت دعا کے طور پر کہتے ہیں.سِرْ عَلَی الطَّائِرِالْمَیْمُوْنِ.کہ مبارک شگون پر چل.اورجب ھُوَ سَاکِنُ الطَّائِرِکہیں تواس کے معنے ہوتے ہیں.حَلِیْمٌ ھَادِیٌ کہ و ہ بردبار متحمل اورسنجیدہ ہے(اقرب)پس اَلْزَمْنٰہُ طَائِرَہٗ فِی عُنُقِہٖ کے معنے ہوں گے کہ ہم نے ا س کے عمل کو اس کی گردن میں باندھ دیا ہے.منْشُوْر مَنْشُوْرٌنَشَرَسے اسم مفعول ہے اور نَشَرَ الْکِتَابَ کے معنے ہیں.بَسَطَہُ.اس کو کھولا (اقرب) پس مَنْشُوْرٌ کے معنے ہوں گے کھولاہوا.تفسیر.اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کاعمل اس کی گردن میں باندھ دیا ہے.یاگردن کے ساتھ چسپاں کردیاہے اورقیامت کے دن اسے اس کے سامنے ایک کتاب کی صورت میںنکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گایعنی اس کے مطابق اس سے سلوک ہوگا.کیونکہ کھاتہ کارجسٹر یاحساب لکھنے کے لئے کھولاجاتاہے یاحساب چکانے کے لئے.انسان کا کوئی فعل ضائع نہیں ہوتا اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہرانسان کو سمجھ لیناچاہیے کہ اس کاکوئی فعل ضائع نہیں ہوتا.کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ اس کاعمل گردن میں چسپاں کردیاہے.گردن میں چسپاں کرنے کے الفاظ یہ بتانے کے لئے استعمال کئے ہیں.کہ اس کے ساتھ اس کاتعلق دائمی ہے.جب تک وہ رہے گا اس کے اعمال کااثربھی رہے گا.عمل کے لئے جو طائر کالفظ استعمال کیاگیا ہے اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جیسے طائراڑجاتاہے اورنظر نہیں آتا.ویسے ہی انسان اپنے عمل کو بھو ل جاتا ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی بھول جاتے ہیں.لیکن یہ طائروہ ہے جو ایک رسی سے انسان کی گردن سے بندھاہواہے.اس لئے گو وہ اُڑجائے اورنظر نہ آئے مگراس سے تعلق انسان کانہیں ٹوٹتا.ایک نہ ایک دن اس کے نتائج ظاہر ہوکرہی رہتے ہیں.دوسرے یہ بتایاہے کہ جیسے پرند ے کے پائوں میںلمبی رسی باندھ کر اسے چھوڑ دیاجاتاہے تووہ رسی کی حد تک اڑ کر چلا جاتا ہے.اسی طرح انسانی اعمال کاحال ہے کہ بعض دفعہ وہ معمولی نظر آتے ہیں لیکن ان کااثر دورتک جاتا ہے.انسانی اعمال کی بندھے ہوئے پرندے سے مشابہت اس آیت میں انسان کو بتایا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال میں بہت ہوشیار اور محتاط رہنا چاہیے.کیونکہ جب کیاہواعمل اسکے اختیار میں نہیں رہتا.اوراس کااثر بھی بہت وسیع ہے.نظروں سے بھی غا ئب ہے اورساتھ بھی لگاہواہے.توان سب باتوں سے معلوم ہوا.کہ اس کامٹانابہت
Page 314
مشکل امر ہے.پس بڑی احتیاط کی ضرورت ہے.اس کے عمل کانتیجہ خوا ہ جلدی نکلے خواہ دیر سے.مگر نکلے گاضرور.کیونکہ گو بعض دفعہ یوں معلوم ہوتاہے کہ وہ پرندہ کی طرح اُڑ گیاہے مگرچونکہ یہ پرندہ گردن سے بندھا ہواہے آخر ایک دن واپس آئے گا.اورانسان کواپنے کئے کامزہ چکھناپڑے گا.دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ فَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ خَیْرًایَّرَہٗ.وَمَنْ یَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ (الزلزال:۸،۹)کہ کوئی شخص اگر سرخ چیونٹی کے برابر بھی نیک یابدعمل کرے گایاہواکے ذرّہ کے برابر بھی نیک یابد عمل کر ے تووہ اس کاانجام ضروردیکھ لے گا.اس آیت کایہ مطلب نہیں کہ توبہ قبول نہ ہوگی توبہ توضرو رقبول ہو گی.مگر گناہ کرنے والاپیچھے ضروررہ جائے گا مثلا ً فرض کرلو کہ دوانسان ہیں جو نیکی میں برابرہیں ان میں سے ایک نے ایک بدی کی.اورپھر توبہ کی.اس کے گنا ہ کو تواللہ تعالیٰ ضرو رمعاف کردے گا.مگر جب اس نے بدی کی.دوسرے شخص نے اس کے مقابل نیکی کی.تویہ توبہ کرنے والاتواسی پہلے درجہ پر رہا.مگر دوسرااس سے آگے نکل گیا.پس اس غلطی کرنے والے شخص کو خدا تعالیٰ معاف تو کردے گا.لیکن یہ نہ ہوگاکہ اس کو اس دوسرے شخص کے ساتھ ملادے جس نے بدی نہیں کی تھی.وہ توبہرحال اس سے ایک درجہ بڑھاہی رہے گا.پس ہرعمل کاایک اثر ہے جو باقی رہتاہے.وائر لیس سے ایک سبق اب تواللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سمجھانے کے لئے انسان کو وائرلیس ٹیلیگرافی یا ٹیلیفون کاعلم بھی بخش دیا ہے.جس سے ثابت ہوتاہے.کہ باریک سے باریک حرکت بھی جوّمیں دورتک مرتعش ہوتی چلی جاتی ہے.ہر عمل بیج کی طرح بڑھتا رہتاہے پس انسان کو اپنے اعما ل میں بہت محتاط ہوناچاہیے.کیونکہ ہرعمل ایک بیج کی طرح ایک نیا پودا پیدا کرتاہے.جوبغیر اس کے علم کے بڑھتا رہتاہے.حدیث میں آتاہے کہ ہرعمل کااثر انسان کے قلب پر ہوتاہے.اگر نیکی کرے تواس کے قلب پر نورکاایک نشان پیداہو جاتا ہے.اوربدی کرے تو ایک سیاہ نشان پڑ جاتاہے.اسی طرح نیکی کرنے والے شخص کے دل پرنیکیوں کانوربڑھتارہتاہے.حتیٰ کہ اس کاسارادل روشن ہو جاتا ہے اوروہ نجات پاجاتاہے اوربدی کرنے والے کے دل پر سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن سارادل سیاہ ہو جاتا ہے اوروہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے.(ابن ماجہ کتاب الزھد باب ذکر الذنوب)بعض لوگوں نے طائر کے معنے قسمت کے کئے ہیں(تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا) مگریہ معنے اس کے نہیں ہوسکتے کیونکہ طٰٓىِٕرَهٗ کہہ کر یہ بتایاگیاہے کہ اپنے عمل کاپیداکرنے والا خود انسان ہی ہے خدا تعالیٰ نے جومقررکردیا.وہ توپتھر کہلائے گا یاطوق طائرہ نہیں کہلاسکتا.
Page 315
یہ معنے بھی اس کے ہوسکتے ہیں کہ ہرانسان کی نیک فالی اوربدفالی تواس کی گردن میں بندھی ہوئی ہے اوروہ دوسری چیزوں میں جاکر فالیں تلاش کرتا پھرتاہے.گردن کالفظ اس لئے استعمال کیا.کہ انسان جب نیکی کرے توسراونچاکرلیتا ہے.اورجب بدی کرے تو ذلت کی وجہ سے گردن نیچی کرلیتا ہے.پس اس لفظ کے استعمال سے اس طرف توجہ دلائی کہ انسان اپنے اعمال کاجائزہ اپنی گردن سے کرلیا کرے(ابن ماجہ کتاب الزھد باب ذکر الذنوب) یعنے دیکھے کہ وہ اپنے ہمرازوں اورہم جلسیوں میں گردن اونچی کرسکتا ہے یانہیں.اگر اس کا دل اوراس کے ہمراز اسے بے عیب قراردیتے ہوں توسمجھ لے کہ اس کاقد م نیکی پر ہے.لیکن اگراس کااپنادل اوراس کے ہمراز اس میں سوسوگند پاتے ہوں تولوگوں میں فخر کرنے سے اسے کیانفع ہو سکتا ہے.وَ نُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا.یہاں کتاب سے مراد جزاء ہے کیونکہ عربی میں کَتَبَ عَلَیْہِ کَذَاکے معنے قَضٰی عَلَیْہِ کَذَاکے ہوتے ہیں.اور يَلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہاں اس کے اعمال کی جزاظاہر ہونے لگ جائے گی.وہ بیج کی طرح نہ رہے گی.بلکہ درخت کی طرح پھیل جائے گی اورپھل پیداکرنے لگے گی.اِقْرَاْ كِتٰبَكَ١ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًاؕ۰۰۱۵ (اوراسے کہا جائے گاکہ)اپنی کتاب (آپ ہی)پڑھ.آج تیرانفس ہی تیراحساب لینے کے لئے کافی ہے.حلّ لُغَات.اَلْحَسِیْبُ اَلْحَسِیْبُ وَالْمُحَاسِبُ : مَنْ یُحَاسِبُکَ.اَلْحَسِیْبُ کے معنے ہیں حساب لینے والا.(مفردات) تفسیر.قیامت میں سب اشیاء اعمال سے متمثل ہوں گی ’’اپنی کتاب کو پڑھ‘‘کے الفاظ کایہ مطلب ہے کہ اب اپنی سزاکوبھگتو.اوریہی سبق دُہراتے رہو.كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.تیرانفس ہی آج تجھ پر کافی حساب لینے والا ہے.اس سے معلو م ہوتاہے کہ سزاباہر سے نہ آئے گی.بلکہ انسان کے اندرسے ہی پیداہوگی.دوزخ میں جتنی چیزیں ہوںگی وہ انسان کے اعمال سے ہی متمثل ہوں گی.اورجنت کی چیزیں بھی اسی طرح نیکیوں سے ہی متمثل ہوں گی.پس گویا کوئی دوسراانسان کسی کوسزایاجزاء نہ دے گا.بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو جزادینے والا اورخود ہی سزادینے والاہوگا.
Page 316
مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ١ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا (پس یاد رکھوکہ)جوہدایت کوقبول کرے گا.تواس کاہدایت پانا اسی کی ذات کے لئے ہے اورجو (اسے ردّ يَضِلُّ عَلَيْهَا١ؕ وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى١ؕ وَ مَا كُنَّا کرکے)گمرا ہ ہوگا.اس کاگمراہ ہونا اسی کے خلاف پڑے گا.اورکوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری (جان ) مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا۰۰۱۶ کابوجھ نہیں اٹھائے گی اورہم (کسی قوم پر)ہرگزعذاب نہیں بھیجتے جب تک (ان کی طرف)کوئی رسول نہ بھیج لیں.حلّ لُغَات.اِھْتَدٰی اِھْتَدٰی ھَدَی سے باب افتعال ہے.اورھَدَی کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر۲۸.(بنی اسرائیل آیت ۳) ضَلَّ کے لئے دیکھو یونس ۳۰(النحل آیت نمبر۸۸) تَزِرُ وَزَرَ سے مضارع مؤنث غائب کاصیغہ ہے.اور وَزَرَہٗ کے معنے ہیں حَـمَلَہُ.اس کو اٹھایا.وَفِی اللِّسَانِ حَـمَلَ مَا یُثْقَلُ ظَھْرُہٗ مِنَ الْاَشْیَاءِ الْمُثْقَلَۃِاس نے بھاری بوجھ اٹھایا (اقرب) وَلَا تَزِرُ وازِرَۃٌ وِزْرَ اُخرٰی کے معنے ہوں گے.کوئی بوجھ اٹھا نے والی جان دوسری جان کابوجھ نہیں اٹھائے گی.اَلْوِزْرُ کی تشریح کے لئے دیکھو نحل آیت نمبر۲۶.تفسیر.اس آیت میںپہلی آیت کے مضمون کی وضاحت کی گئی ہے.اوربتایا گیا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اس کے فائدہ کاموجب ہوتے ہیں.اوربداس کے نقصان کا.پس جو کچھ انسان کرتا ہے دوسرے کے لئے نہیں کرتا اپنے لئے کرتا ہے.قاتل دوسرے کونہیں اپنے آپ کو قتل کرتا ہے.ظالم دوسرے پر نہیں اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے.چور دوسر ے کا نہیں اپنا مال چراتا ہے.اسی طرح صدقہ کرنےوالا دوسرے کو نہیں دیتااپنے آپ کودیتاہے.دوسرے کوتعلیم دینے والا یاہدایت دینے والا اسے تعلیم نہیں دیتایاہدایت نہیں دیتا بلکہ اپنے آپ کو تعلیم دیتاہے اوراپنے آپ کو ہدایت دیتا ہے.اس کے آگے فرماتا ہے کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى.کوئی بوجھ اٹھانے والی جا ن کسی اورجان کا بوجھ نہیں اٹھا
Page 317
سکتی.عیسائی اس آیت سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ لوکفارہ ثابت ہوگیا.کیونکہ ہم بھی یہی کہتے ہیں.کہ گناہ گار گناہ گار کابوجھ نہیںاٹھاسکتا.مگر جو نیک ہے و ہ دوسرے کا بوجھ اٹھاسکتا ہے.پس مسیح جونیک تھا.اس نے دوسروں کے بوجھ اٹھالئے اوردوسراکو ئی نیک نہیں.پس اورکوئی بوجھ نہیں اٹھاسکا.کفار ہ کا ردّ میں اس جگہ اس سوال میں نہیں پڑتاکہ مسیحی عقیدہ کے رُو سے مسیح نیک تھا یانہیں.نہ اس سوال میں پڑناچاہتاہوںکہ اسلامی عقید ہ کے روسے مسیح کے سوابھی کوئی نیک ہے یانہیں.اس کی تفصیل کایہ موقعہ نہیں.اس وقت ان کے جواب میں یہ کہنا چاہتاہوں کہ اس آیت میں توصرف یہ بتایا گیا ہے کہ خواہ انسانی اعمال برے ہوں یا اچھے.خود اس کے لئے ہوتے ہیں انہیںکوئی دوسر انہیں اٹھاسکتا.مطلب یہ کہ سزاجزاء کوئی بیرونی شے نہیں بلکہ ثمرئہ عمل کانام ہے.اوریہ ظاہر ہے کہ جس جگہ بیج بویا گیا ہے وہیں وہ پھل دے گا.دوسری جگہ وہ پھل نہیں دے سکتا ایک آم جو لاہور میں لگا ہو امرتسر میں پھل نہیں دے سکتا.پس جب سزاجزاء خود عمل کرنے والے کے نفس سے پیداہوتی ہے تواسے کوئی دوسرانہیں بانٹ سکتا یااپنے ذمہ نہیں لے سکتا.پس اس مضمون میں کفار ہ کا رد ہے نہ کہ اس کی تائید.کفار ہ کی بنیاد تواس خیا ل پر ہے کہ سزاایک بیرونی بوجھ کی طرح ہے.پس دوسراشخص بھی اسے اٹھا سکتاہے.مگر ا س آیت میں ا س عقیدہ کورد کیا گیا ہے.عیسائیوں کا دوزخ کو مادی قرار دینا حماقت ہے اسی اعتراض سے بچنے کے لئے مسیحیو ں نے دوزخ کو مادی قرار دیا ہے(Catechism of Christian Doctrine vol:2 p.599).حالانکہ یہ حماقت کی بات ہے کہ جنت توروحانی ہو.اوردوزخ مادی ہو.یادونوں روحانی ہوںگی یا دونوں مادی.اگرروحانی ہوں گی توپھر کو ئی شخص کسی دوسرے کی سزانہیں اٹھاسکتا.کیاکوئی شخص دوسرے کی ندامت ،حرص، رنج ،غضب وغیر ہ کو بانٹ سکتا ہے ؟ اسی لئے نہیں بانٹ سکتاکہ یہ چیز یں انسان کے اندر سے پیداہوتی ہیں.اوران کے پیداکر نے میں خود اس کے نفس کادخل ہوتا ہے اس قسم کی سزااسی صورت میں مٹ سکتی ہے جب نفس حقیقتاً فناہوجائے یامعنوی طور پر فنا ہو جائے.یعنی ندامت کے احسا س کے ساتھ اس میں پاکیز گی پیداہوجائے.اس قسم کی فنا میں کوئی دوسراشخص کسی طرح بھی شریک نہیں ہوسکتا.کوئی معقول آ دمی کسی دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا.کہ میا ں بہت شرمندہ نہ ہو میں تمہاری جگہ شرمندہ ہولیتا ہوں.ایک فاترالعقل ہی ایسا کہہ سکتا ہے.پھر کیوں مسیحی خداکے برگزیدہ مسیح کے منہ سے یہ الفاظ کہلا کر اس کی ہتک کرتے ہیں.وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.اورہم سزانہیں دیاکرتے.یہاں تک کہ ہم ایک رسول بھیج لیں.
Page 318
اس کے متعلق قرآن کریم میں دوسری جگہ آتاہے.كُلَّمَاۤ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ.قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ(الملک:۹،۱۰)کہ جب کبھی کوئی گروہ اورقوم جہنم میں ڈالی جائے گی.توان سے دریافت کیاجائے گاکہ تمہار ے پاس کوئی ڈرانے والاآیا.تووہ کہیں گے کہ ہاں.ہمارے پاس نبی آیا.اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہرقوم میں نبی آئے.اسی طرح ایک اورجگہ فرمایا ہے.اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ۠ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا(الزمر:۷۲)کہ کیا تمہارے پاس رسول نہ آتے رہے جو تم کو اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے.ایک اورجگہ فرماتا ہے.اَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ (الفاطر :۳۸)کیاتم کو ہم نے اس قدر عمر نہیں دی کہ جس کی سمجھنے کی نیت ہوتی.اس میں سمجھ سکتاتھا اورپھر اسی پر بس نہیں کی.بلکہ تمہارے پاس ہوشیار کرنے کے لئے رسول بھی بھیجے.اسی طرح قصص رکوع ۶ میں فرماتا ہے وَمَاکَانَ رَبُّکَ مُھْلِکَ الْقُرٰی حَتّٰی یَبْعَثُ فِیْ اُمِّھَا رَسُوْلًا(آیت :۶۰).تیرے خدا کی شان کے خلا ف ہے کہ وہ اس کے مرکزی مقام میں نبی بھیجے بغیر کسی بستی کو ہلاک کردے.اورپھر سورہ قصص ع ۵ میں فرمایا وَلَوْلَٓااَنْ تُصِیْبَہُمْ مُّصِیْبَۃٌ بِمَاقَدَّمَتْ اَیْدِیْھِمْ فَیَقُوْلُوْارَبَّنَا لَوْلَٓااَرْسَلْتَ اِلَیْنَارَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰیٰتِکَ وَ نَکُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ (آیت :۴۸) یعنی اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ ان لوگوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی عذاب پہنچا.تویہ کہہ دیں گے کہ اے ہمارے رب کیوں نہ آپ نے ہماری طرف رسول بھیجاکہ ہم ذلیل وخوار ہونے سے پہلے آپ کے احکام کی تعمیل کرتے.توہم ان کو بغیر رسول بھیجے کے ہی عذاب دے دیتے مگرچونکہ یہ عذر ا ن کامعقو ل ہوتا.ہم نے اس عذر کوتوڑ دیا ہے.اورہمیشہ پہلے رسول بھیجتے ہیں.پھر اس کے انکا ر کے بعد عذاب لاتے ہیں.ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت الٰہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر رسول بھیجنے کے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا.یعنی اتنے وسیع علاقہ پر جونبیءِ وقت کا مخاطب ہو اس وقت تک عذاب نہیں آتا.جب تک پہلے ایک اورنبی خواہ وہ پہلے نبی کاتابع ہی کیوںنہ ہو ظاہر ہو کر لوگوں کو ہوشیار نہ کردے.دنیا میں جن پر حجت تمام نہیںہوتی ان کے لئے قیامت میں بعثت رسول یہاں سوال ہوسکتا ہے کہ وہ لو گ جن پر حجت تمام نہیں ہو ئی ان کا کیا حا ل ہوگا.تواس کا جواب مسند احمد بن حنبل کی روایت میں ہے جو ابوہریرہؓ نے بیان کی ہے اِنَّ النَّبِیَ صَلَّے اللہُ تَعَالیٰ عَلَیْہ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعَۃٌ یَحْتَجُّوْنَ یَوْمَ الْقَیَامَۃِ رَجُلٌ اَصَمُّ لَایَسْمَعُ شَیْئًاوَرَجُلٌ اَحْمَقُ وَرَجُلٌ ھَرَمٌ وَرَجُلٌ مَاتَ فِی فَتْرَۃٍ فَاَمَّا الْاَصَمُّ فَیَقُولُ رَبِّ لَقَدْ جَآءَ الْاِسْلَامُ وَمَااَسْمَعُ شَیْئًا وَاَمَّاالْاَحْمَقُ فَیَقُوْلُ جَآءَ الاِسْلَامُ وَالصِّبْیَانُ یَخْذِفُوْنَنِیْ بِالْبَعْرِ وَاَمَّا
Page 319
الْھَرَمُ فَیَقُوْلُ رَبِّ لَقَدْ جَاءَ الْاِسْلَامُ وَمَا اَعْقِلُ شَیْئًاوَاَمَّاالَّذِیْ مَاتَ فِی الْفَتْرَۃِ فَیَقُوْلُ رَبِّ مَااَتَانِیْ لَکَ رَسُوْلٌ فَیَاخُذُ سُبْحَانَہُ مَوَاثِیْقَہُمْ لَیُطِیْعُنَّہُ فَیُرْسِلَ اِلَیْھِمْ رَسُوْلًااَنِ ادْخُلُواالنَّارَ فَمَنْ دَخَلَہَا کَانَتْ عَلَیْہِ بَرْدًاوَسَلَامًا وَمَنْ لَمْ یَدْخُلْہَا سُحِبَ اِلَیْہَا(روح المعانی زیر آیت ھذا) یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے پاس رسول بھیجے گا پھر اس کی اطاعت کرنے والوں اوراس کو نہ ماننے والوں کی فطرت ظاہر ہوجائے گی.اوراس کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا.وَ اِذَاۤ اَرَدْنَاۤ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا اورجب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کاارادہ کریں تو(پہلے)ہم اس کے خود سر لوگوں کو (کچھ )حکم دیتے ہیں جس پر وہ فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ اس (بستی )میں نافرمانی (کی راہ اختیار)کرتے ہیں.تب اس (بستی)کے متعلق ہماراکلام پوراہو جاتا ہے.فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا۰۰۱۷ اورہم اسے پوری طرح تباہ کردیتے ہیں.حلّ لُغَات.مُتْرَفِیْھَا.اَلْمُتْرَفُ کے معنے ہیں.اَلْمُتَنَعِّمُ لَایَمْنَع مِنْ تَنَعُّمِّہِ.عیاش.اَلْمَتْرُوْکُ یَصْنَعُ مَایَشَاءُ.شریعت سے آزاد شخص.اَلْجَبَّارُ.خودسر(تاج) مُتْرَفُوْنَ اس کی جمع ہے.فسقوا فَسَقُوْا فَسَقَ سے جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۳۴.فَسَقَ الرَّجُلُ فِسْقًا: تَرَکَ اَمْرَاللہِ.اللہ کی نافرمانی کی.عَصَی نافرمان ہو گیا.جَارَعَنْ قَصْدِ السَّبِیْل.درست راہ سے روگردان ہو گیا.فَجِرَ.بدکردار ہو گیا.خَرَجَ عَنْ طَرِیْقِ الْحَقّ.حق کی راہ سے الگ ہو گیا.اَلرُّطْبَۃُ عَنْ قِشْرِھَا خَرَجَتْ گابھا چھلکے سے باہر آگیا.(اقرب) دمَّرنا:دَمَّرْنَا دَمَّرَ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے اوردَمَّرَھُمْ (وَعَلَیْھِمْ )کے معنے ہیں اَھْلَکَہُمْ یعنے دَمَّرَ جب بغیر صلہ یاعلیٰ کے صلہ کے ساتھ استعما ل ہو.تواس کے معنے ہوتے ہیںکہ اس کو ہلاک کردیا (اقرب)پس دَمَّرْنَا کے معنی ہوں گے ہم نے ہلا ک کردیا.
Page 320
تفسیر.خدا کا عذاب قوموں کے خراب ہونے پر آتا ہے اس آیت میں بتایاگیاہے کہ جب قومیں خراب ہوجاتی ہیں اوران کے عذاب کافیصلہ ہو جاتا ہے توان کی طرف ایک رسول بھیجا جاتاہے جوان کو ہوشیار کرتاہے لیکن لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے اور رسول سے ٹھٹھاہنسی کرتے ہیں.اوراس کی نافرمانی کرتے ہیں.تب خدا تعالیٰ کاعذاب انہیں آپکڑتاہے.اَمَرْنَا مُتْرَفِیْہَا فَفَسَقُوْافِیْہَا.بعض مخالفین اسلام نے ا س آیت کے یہ معنے کئے ہیں کہ خدا تعالیٰ بڑے بڑے لوگوںکو یہ حکم دیتاہے کہ بدکار ہوجائو.اوریہ غلط معنے کرکے ا س پر اعتراض کیا ہے کہ آپ ہی پہلے گمراہ کیاپھر عذاب میں مبتلاکردیا یہ توانصا ف کے خلاف ہے.حالانکہ فسق کے معنے حکم نہ ماننے کے ہیں اوران معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جومعنے انہوں نے کئے ہیں ان کی بناء پر آیت کاترجمہ یو ں بنتاہے کہ خدا تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم بدکاری کرو.فَفَسَقُوْافِیْہَا تووہ ا س حکم کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں.ظاہر ہے کہ اگر آیت کا مطلب یہ ہو تو اس میں تو ان لوگوں کی تعریف نکلتی ہے کہ باوجود خدا تعالیٰ کے کہنے کے کہ بدکار بن جائو وہ بدکار نہیں بنتے.بلکہ نیک ہو جاتے ہیں.اوریہ معنی بالبداہت غلط ہیں اوراگر یہ معنے کئے جائیں کہ خداکے بدکار بنانے پر وہ بدکار ہوجاتے ہیں تو فَسَقُوْاکا لفظ در ست نہیں رہتا کیونکہ اس صورت میں تووہ فرمانبرداربن جاتے ہیںان کو نافرمان نہیں کہاجاسکتا غرض یہ معنے بالبداہت غلط ہیں اور عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے کئے گئے ہیں.اوراعتراض قرآن کریم پر نہیں پڑتا.بلکہ ان لوگوںکے علم پر پڑتا ہے.اصل مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ہم ان کو حکم دیتے ہیں یعنی بعض خاص امور پر چلنے کاحکم دیتے ہیں جوحکم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے سبب سے بہرحال نیکی کاحکم ہوتا ہے.مگر وہ نافرمان ہو جاتے ہیں یعنے اس حکم کو نہیں مانتے.غرض اس جگہ اَمَرْنَا کامفعول ثانی محذوف ہے کیونکہ وہ ایک ظاہر بات ہے اورایسے مواقع پر عربی زبان میں ایک یادونوں مفعولوں کومحذوف کردیناجائزہوتاہے.مفعول ثانی کا مضمون ظاہر اس طرح ہے کہ قرآن کریم نے بار بار اس امر کو بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ جب حکم دیتا ہے نیکی کاحکم دیتا ہے.چنانچہ سورئہ نحل رکوع ۱۳میں ہی فرماچکا ہے کہ اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَآئِ ذِیْ الْقُرْبٰی وَیَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآئِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ (النحل:۹۱)یعنے اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اوراس نیکی کاجس میں بدلہ کاخیال تک بھی دل میں نہیں ہو تاحکم دیتاہے اورباطنی بدی اورظاہری بدی اورظلم سے روکتاہے.اسی طرح سورئہ اعراف میں ہے.قُلْ اِنَّ اللّٰہَ لَایَاْمُرُ بِالْفَحْشَآئِ (الاعراف :۲۹)تُو کہہ دے اللہ تعالیٰ ہرگز بدی کاحکم نہیں دیتا.پس چونکہ یہ امر واضح ہوچکاہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا ہی حکم دیتاہے.مفعول ثانی کومحذوف کردیاگیاہے اورمطلب آیت کا یہ ہے کہ جب
Page 321
اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلا ک کرنے کاارادہ کرتاہے تووہ ا س قوم کو ایک رسول کے ذریعہ سے نیک احکام پرچلنے کاحکم دیتا ہے مگربجائے اس حکم سے فائدہ اٹھانے کے و ہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑ ھ جاتے ہیں.مُتْرَفٌ کے معنے یہ جو فرمایا ہے کہ اَمَرْنَا مُتْرَفِیْہَا کہ ہم اس بستی کے مترفوں کوحکم دیتے ہیں.اس کے یہ معنی نہیں کہ صرف مالداروں کوخدا کاحکم ملتا ہے بلکہ مترف کے معنے اس جگہ اَلَّذِیْ یَصْنَعُ مَایَشَآئُ وَلَا یَمْنَعُ کے ہیں یعنی ایسا شخص جو اپنی مرضی پرچلتاہے اورنیک بات کونہیں مانتااوراس لفظ میں سب کے سب وہ لوگ شامل ہیں جوبدی میں مبتلاہوتے ہیں خواہ غریب ہوں یاامیر.اس آیت کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ ہم عام حکم دیتے ہیں مگرمترف یعنی باغی لوگ اس کونہیں مانتے نیک لوگ مان لیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیساکہ شیطا ن کے بارہ میں فرمایا ہے کہ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ (الاعراف :۱۳) کہ تجھے کس چیز نے سجدہ سے روکا تھا.جب میں نے تجھے حکم دیاتھا.یہاں یہ مراد نہیں کہ خاص اسے ہی حکم تھا بلکہ حکم عام تھا.جس میں وہ بھی شامل تھا.پس جب نبی آتا ہے تووہ عام حکم لاتا ہے.ماننے والے مان جاتے ہیں اورانکار کرنے والے انکا ر کرتے ہیں.قریہ سے مراد ام القری قریہ سے مراد یہاں پربستی نہیں بلکہ ام القریٰ مراد ہے یعنی جس بستی کو اس زمانہ کے لئے خدا تعالیٰ نے مرکز تجویز کیا ہو.جیساکہ قرآن میں ایک اورجگہ فرمایا ہے حَتّٰی یَبْعَثَ فِیْ اُمِّھَا رَسُوْلًا(القصص:۶۰).کہ ہم عذاب نازل کرنے سے پہلے ام القریٰ میں رسول بھیج لیتے ہیں.وَ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ١ؕ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ اور(اسی قانون کے مطابق)ہم نے نوح (کی قوم کو اور اس)کے بعد (یکے بعد دیگرے اور)بہت سی نسلوں کوہلاک بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا۰۰۱۸ کیا اورتیرارب اپنے بندوں کے گناہوں پر (اچھی طرح )آگاہی رکھنے والا ہے (اورانہیں)خوب دیکھتاہے.حلّ لُغَات.القرون القُرُوْنُکے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۱۴.اَلْقَرُوْنُ اَلْقَرْنُ کی جمع ہے.اس کے کئی معنی ہیں.کُلُّ اُمَّۃٍ ہَلَکَتْ فَلَمْ یَبْقَ مِنْھُمْ اَحَدٌ ہر ایسی قوم جو تمام کی تمام ہلاک ہوئی اور اس میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا.اَلْوَقْتُ مِنَ الزَّمَانِ زمانہ کے ایک حصہ کو بھی قَرْنٌ
Page 322
کہتے ہیں.اَھْلُ زَمَانٍ وَاحِدٍ ایک زمانہ یا ایک نسل کے لوگوں کو بھی قرن کہتے ہیں.اُمَّۃٌ بَعْدَ اُمَّۃٍ.زمانہ کے دور کو بھی کہتے ہیں.اور اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے بعد آرہی ہے.عربی کا ایک محاورہ قَرْنُ الشَّیْطَانِ بھی ہے اور اس کے بھی دو معنی ہیں.اَلْمُتَّبِعُوْنَ لِرَأْیِہٖ.شیطانی لوگ.تَسَلُّطُہُ.شیطان کا تسلط.(اقرب) تفسیر.یعنی اس قسم کی مثالیں تم کو شروع سے دنیامیں نظرآئیں گی نوح سے لے کر اس وقت تک نبی آتے رہے ہیں سب کے زمانہ میں اسی طرح ہوتاچلاآیا ہے.وَ كَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جوخبیر و بصیر ہے بندوں کو غلط راستہ پر چلتے دیکھ کر کس طر ح خاموش رہ سکتاہے.یہ فقرہ بھی ان معنوں کو رد کرتا ہے جو اوپر کی آیت کے بعض نادانوں نے کئے ہیں.کیونکہ اس میں بتایا ہے کہ معذب لوگ پہلے سے گنہ گار ہوتے ہیں یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو گنہ گا ر بناتا ہے.مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ جوشخص (صرف )دنیاکاخواہاں ہو ہم اسے (یعنی ایسے لوگوںمیں سے)جس کے متعلق ہم (کچھ دینے کا)اراد ہ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ١ۚ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا کرلیتے ہیں.اس (دنیا)میں جوکچھ چاہتے ہیں جلد(ہی)دےدیتے ہیں.پھر ہم اس کے لئے جہنم کو مخصوص مَّدْحُوْرًا۰۰۱۹ کردیتے ہیںجس میں و ہ مذموم ہوکر(اور)دھتکاراجاکر داخل ہو گا.حلّ لُغَات.اَلْعَاجِلَۃُ.اَلْعَاجِلَۃُ عَاجِلٌ (اسم فاعل عَجَلَ)سے مؤنث ہے.اورعَجَلَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں.اَسْرَعَ.اس نے جلدی کی.نیز اَلْعَاجِلَۃُکے معنے ہیں اَلدُّنْیَا.دنیا (اقرب) قَوْلُہٗ مَنْ کَانَ یُرِیْدُ الْعَاجِلَۃَ اَیْ اَلْاَعْرَاضَ الدُّنْیَوِیَّۃُ آیت مَنْ کَانَ یُرِیْدُ الْعَاجِلَۃَ میں اَلْعَاجِلَۃَ سے مراد دنیوی سامان ہیں (مفردات) جہنّمجَہَنَّمَ کےلئے دیکھو رعدآیت نمبر ۱۹.
Page 323
جَھَنَّم: دَارُالْعِقَابِ کا نام ہے.یہ ممنوع من الصرف ہے.بعض کے نزدیک یہ لفظ عجمی ہے.بعض اسے اصل میں فارسی یا عبرانی قرار دیتے ہیں لیکن یہ درست نہیں کہ عربی کے الفاظ کو غیرزبانوں کی طرف منسوب کیا جائے.بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لفظ ایسے قاعدہ سے بنایا گیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی.اس وجہ سے اس کو انہوں نے غیرزبان کا قرار دے دیا.عربی میں جَھَنَ جُھُوْنًا کے معنے قَرُبَ وَدَنَا کے ہوتے ہیں اوراِس سے جَھَنَّمُ بنا ہے یا یہ لفظ جَھَمَ سے بنا ہے.عربی زبان میں زِیَادَۃُ نُوْنٍ فِی وَسْطِ الْکَلِمَۃِ کی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں.پس جَھَمَ سے جَھَنَّمُ کا بننا خلاف قواعد نہیں اور جَھَمَ کے معنے ہیں اِسْتَقْبَلَہٗ بِوَجْہِ مُکْفَھِّرٍ.کہ اس کو تیوری چڑھا کرملا اور تَـجَھَّمَہٗ کے معنے ہیں اِسْتَقْبَلَہٗ بِوَجْہٍ کَرِیْہٍ برے چہرے سے ملا.(اقرب) پس جَھَنَّمَ کے معنے ہوئے ایک ناپسندیدہ جگہ جو ناراضگی سے لینے کو بڑھتی ہے.یہ نام اس کے شعلے مارنے کی وجہ سے رکھا گیا.مَدْحورًا.مَدْحُوْرًا دَحَرَ(یَدْحَرُ.دُحُوْرًا)سے اسم مفعول ہے.اور دَحَرَ کے معنے ہیں.طَرَدَہُ.اس کو دھتکارا.اَبْعَدَہٗ.اس کو دورکیا.دَفَعَہٗ.اس کوہٹایا.(اقرب)پس مَدْحُوْرٌ کے معنے ہوں گے (۱)دورکیا ہوا (۲)دھتکاراہوا (۳)ہٹایاہوا.تفسیر.اس آیت میں بتایاہے کہ قریب کے فائدہ کو مدنظر نہیں رکھنا چاہیے.بلکہ ایسے فائدہ کومدنظر رکھنا چاہیے جوبابرکت ہو.خوا ہ بعد میں ہی ملے.دوسرے یہ بتایاہے کہ صرف دنیوی ترقیات کوخدا کافضل نہیں قراردینا چاہیے.کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو دنیوی ترقیات دیتاہے.لیکن وہ ان پر خوش نہیں ہوتا.فضل الٰہی وہی ترقیات کہلا سکتی ہیں جن کے ساتھ روحانیت میں ترقی ہو.وَ مَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَ سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ اورجس شخص نے آخر ت کی خواہش کی اوراس کے لئے اس کے مطابق کو شش (بھی)کی تو(اس کے متعلق یاد رکھو فَاُولٰٓىِٕكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا۰۰۲۰ کہ)ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قد رکی جائے گی.تفسیر.سعی مشکور ہی کارگر ہوتی ہے.سَعْیَھَامیں ھَا کی ضمیر آخرت کی طرف پھر تی ہے.
Page 324
اورمطلب یہ ہے کہ ایسی کوشش کرتے ہیں.جوآخرت کے حصول کے مناسب حا ل ہو.اس میں اس طرف اشارہ کیاہے کہ عام کوشش مفید نہ ہوگی.بلکہ وہ کوشش فائدہ بخش اورنتیجہ خیز ہوگی جواخروی کامیابی کے مناسب حال ہوگی.وَھُوَمُؤمِنٌ کہہ کریہ بتایاہے.کہ حیات آخرت کا مدار قلب کی صفائی پر ہے.دنیوی کام بعض دفعہ بغیر ایمان کے بھی نفع بخشتے ہیں.لیکن آخرت کے لئے جوکوشش ہو.اس میں وہی کام نفع دیتاہے جس کے ساتھ ایمان بھی ہو.سَعْیٌ مَشْکُوْرٌ کے معنے مَشْکُوْرٌ کے معنے مقبول کے ہیں.یعنی وہی خداکے ہاں مقبول ہوگا.جس کے ساتھ ایمان شامل ہو.وَھُوَ مُوْمِنٌ کا یہ مطلب نہیں کہ مومن کے سواکسی کی نیکی قبول نہیں.بلکہ یہ مرا دہے کہ اُخروی جزاء پر ایمان رکھتے ہوئے جونیک عمل کرے اُسے اُخروی جزاملے گی.جواس پر ایمان لانے کے بغیر نیک عمل کرے اس کے عمل کابدلہ اُسے اسی دنیا میں مل جائے گا.كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَ هٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ١ؕ وَ مَا كَانَ ہم سب کو مدددیتے ہیں.ان کو بھی او ر ان کو بھی (اوریہ مدد)تیرے ر ب کی عطائوں میں سے ہے.اورتیرے عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا۰۰۲۱ رب کی عطا(کسی خاص گروہ کے لئے )محدود نہیں ہے.حلّ لُغَات.نُمِدُّ:نُمِدُّ اَمَدَّسے مضارع جمع متکلم کاصیغہ ہے.اوراَمدَّہُ کے معنے ہیں.اَمْھَلَہُ اسے مہلت دی.اَمَدَّ اَجَلَہٗ:اَخَّرَہٗ.اس کی میعاد لمبی کی.اَمَدَّ الْجُنْدَ:نَصَرَھُمْ بِجَمَاعَۃٍ.کمک بھیج کر ان کی مدد کی.اَمَدَّ فُلَانًا بِمَالٍ:اَعْطَاہُ.اس کومال دیا.اَعَانَہٗ وَاَغَاثَہٗ.اَمَدَّ کے ایک معنے مدد کرنے اورفریاد رسی کر نے کے ہیں (اقرب)پس نُمِدُّ کے ایک معنے ہوں گے ہم مدد دیتے ہیں.المَـحْظُوْر اَلْمَحْظُوْرُ اَلْمَمْنُوْعُ.محظور کے معنے ہیں.روکاہوا.اَلْمُحَرَّمُ وَمِنْہُ فِی الْقُرْاٰنِ وَمَاکَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُوْرًااَیْ مُـحَرَّمًا اورمحظور کے ایک معنے حرام کئے ہوئے کے بھی ہیں.اورآیت مَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ
Page 325
مَحْظُوْرًامیں محظورکے معنے یہی لئے گئے ہیں.وَقِیْلَ مَقْصُوْرًاعلیٰ طَائِفَۃٍ دُوْنَ اُخْرٰی مِنْ حَظَرَ الشَیءَ اِذَاحَازَہُ لِنَفْسِہِ.اوربعض نے کہا ہے کہ چونکہ حظر کے ایک معنی کسی چیز کواپنے نفس کے لئے مخصوص کرنے کے ہیں.اس لئے محظور کے معنے یہ ہوں گے کہ ایک گروہ کے ساتھ مخصوص کی ہو ئی.(اقرب) تفسیر.پہلی آیت سے جوشبہ پیدا ہوتاتھا.کہ شاید مومن کے بغیر کسی کو نیک جزاء نہیں ملتی.اس کاازالہ اس آیت میں کیا گیا ہے اوربتایا ہے کہ نصرت الٰہی دو قسم کی ہوتی ہے.ایک وہ جومذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی بلکہ عام ہوتی ہے.جوکام کوئی کرتاہے اورجس کسی کام کے لئے کوئی کوشش کرتاہے.ا س کے مطابق اس کو پھل ملتا ہے.اس میں ہندو.مسلمان.عیسائی.موسائی وغیر ہ کی کوئی قید نہیں.اور ایک ایسی نصرت ہوتی ہے جو مذہب کے نتیجہ میں ہوتی ہے.وہ صرف مومن کے شامل حال ہوتی ہے اورکافر کونہیں ملتی.اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ١ؕ وَ لَلْاٰخِرَةُ دیکھ کس طرح ہم نے (دنیوی سامانوں کی روسے بھی)ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی (ہوئی )ہے.اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا۰۰۲۲ اورآخرت (کی زندگی)تویقیناً(اوربھی )بڑے درجات والی اورزیادہ فضیلت والی(زندگی) ہوگی.تفسیر.جنت میں مدارج اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّ اَكْبَرُ تَفْضِيْلًا.فرمایا آخر ت تودرجات اورفضیلت دینے میں بہت بڑی ہے.مسلم کی ایک حدیث ہے.عَنْ اَبِی سَعِیْدٍ الخُدْرِیِّ اَنّ رَسُوْلَ اللہِ صَلّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَھْلَ الْجَنّۃِ لَیَتْرَاءَ وْنَ اَھْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِھِمْ کَمَاتَتْرَاءَ وْنَ الْکَوْکَبَ الدُّرِّیَ الْغَابِرَ مِنَ الْاُفُقِ مِنَ الْمَشْرقِ اَوِالْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَیْنَہُمْ(مسلم کتاب الجنۃ وصفۃ نعیمہا واھلھا باب ترائی أھل الجنة أھل الغرف ) کہ بڑے بڑے درجات والے اپنے سے اوپر والے جنتیوں کواسی طرح دیکھیں گے جیسے تم اس ستارہ کو دیکھتے ہو جودوراُفق میںہوتاہے اوریہ ان کے مدارج کے فرق کی وجہ سے ہوگا.ا س آیت میں پہلی آیت کے مضمون کاثبوت پیش کیا ہے.اوربتایا ہے کہ دیکھ لو دنیا میں ہم نے بہت سے لوگوںکو جومومن نہیں ترقیات دی ہیں یہ ان کے اعمال کے قبول ہونے کے سبب سے ہی ہے انہوں نے دنیا کے لئے محنت کی.دنیا ہم نے ان کو دے دی.مگر اس سے یہ دھوکہ نہ کھاناچاہیے کہ غیرمومن بھی اعلیٰ ترقیات حاصل کرلیتے
Page 326
ہیں کیونکہ یہ اُخروی ترقیات کے مقابل پر حقیر ہیں.اس آیت میں مومنوں کو نیکی میں بڑھنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے اوربتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ہاں بڑے بڑے انعامات ہیں.پس نیکی کے کسی مقام پرکھڑانہیں ہوجانا چاہیے.لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًاؒ۰۰۲۳ پس اللہ (تعالیٰ)کے ساتھ کوئی دوسرامعبود نہ بنائیو ورنہ تومذموم ہوکر (اور)نصرت (الٰہی)سے محروم ہوکر بیٹھ جائے گا تفسیر.مشرکین کے ترقی نہ کر سکنے کی وجہ ا س میں یہ دلیل ہے کہ کیوں اُخروی نعماء بغیر ایمان کے نہیں ملتیں.اوروہ دلیل یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ وابستہ ہوگا اسی کے ساتھ جائے گا.پس جو خدا تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تواللہ تعالیٰ کے ساتھ آگے آگے بڑھتے جائیں گے.لیکن جو اللہ تعالیٰ سے وابستہ نہیں بلکہ جھوٹے معبوودں کے ساتھ وابستہ ہیں وہ وہیں بیٹھے رہیں گے جہاں ان کے معبود ہیں.یاد رہے کہ شرک کے ساتھ انسان نیچے ہی نیچے گرجاتا ہے.دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم ایسی نہ ملے گی جو شرک کواختیار کرکے ترقی کرگئی ہو.مشرک قو م جب ترقی کرے گی اپنے مذہب سے بیگانہ ہوکر ترقی کرے گی اس کے اصول پر چلتے ہوئے کبھی ترقی نہ کرے گی.وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ۠ اِحْسَانًا١ؕ تیرے رب نے (اس بات کا)تاکیدی حکم دیا ہے.کہ تم اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو اور(نیز اپنے )ماں باپ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ سے اچھا سلوک کرنے کا اگر ان میں سے کسی ایک پر یاان دونوں پر جب کہ وہ تیرے پاس ہوں بڑھاپا آجائے تو لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا انہیں(ان کی کسی بات پرناپسندیدگی کااظہار کرتے ہوئے )اف تک نہ کہہ اورنہ انہیں جھڑک اوران سے
Page 327
قَوْلًا كَرِيْمًا۰۰۲۴ شریفانہ طورپر نرمی سے بات کر.حلّ لُغَات.قضٰی.قَضٰی عَلَیْہِ عَھْدًا اَوْصَاہُ.اس کو تاکیدی حکم دیا.قَضَی الْعَھْدَ:اَنْفَذَہُ.عہدواقرار کو جاری کیا.اِلَیْہ الْاَمْرَ :اَنْھَا ہٗ وَاَبْلَغہٗ.اس تک کسی امر کو پہنچایا.وَفِی الْاَسَاسِ قَضٰی اِلَیْہِ اَمْرً وَعَھْدًا: وَصَّاہُ بِہِ وَاَمَرَہُ بِہٖ.اوراساس میں قضٰی اِلَیْہِ اَمْرًا کے معنے یہ کئے گئے ہیں کہ اسے تاکید ی حکم دیا.(اقرب) اُفّ.اُفٍّناپسندیدگی.بے قرار ی اورحقار ت کے اظہار کے لئے یہ لفظ استعمال کیاجاتا ہے(اقرب) لاتَنْھَرْھُمَا لَاتَنْھَرْھُمَانَھَر سے نہی مخاطب کاصیغہ ہے.اور نَھَرَ السَّائِلَ کے معنی ہیں.زجَرہٗ.سائل کو جھڑکا (اقرب) پس لَاتَنْھَرْھُمَا کے معنے ہوں گے کہ انہیں نہ جھڑک.قولًا کریمًا قَوْلًا کَرِیْمًاای سھلًا لیّنًا.نرم پسندید ہ بات.(اقرب) تفسیر.اب اللہ تعالیٰ وہ ترکیب بتاتا ہے جس کے ذریعہ سے انسان اپنے نظام کو محفوظ رکھ سکتاہے.چنانچہ قرآن کریم کی تعلیم کاخلاصہ بیان کرتے ہوئے ا س بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہدایت کے دنوں میں ان احکام کی پابندی کرنا اور ان کاخیال رکھنا.تب ہی تم تنزّل سے بچ سکو گے.ورنہ ترقیات قائم نہ رہ سکیں گی.قرآ ن مجید نے سب سے مقدم حکم توحید کے قیام اورشرک کے ردّکا دیا ہے.جب دنیا میںحکومتیں ملتی ہیں توساتھ ہی توہم پرستی اورشرک بھی پیداہوجاتے ہیں.اس لئے جہاں ترقیات کی پیشگوئی کی وہاں آئندہ کے خطرات سے بھی بچنے کاحکم دیا.اوران سے آگاہ کردیا.توحید کو اس لئے مقدم رکھا ہے کیونکہ کوئی گناہ بغیر شرک کے پیدا نہیں ہوتا.سب گناہ شرک کی شاخیں ہیں میرے نزدیک سب گناہ دراصل شرک ہی کی شاخیں ہیں.گناہ کا مرتکب انسان اسی لئے گناہ کامرتکب ہوتاہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات اورصفات پر کامل ایمان اورتوکل نہیں رکھتا.توحید کامسئلہ نیکیوں کے لئے بطورایک بیج ہے.تمام مذاہب اور تما م اخلاق اسی مرکز کے گرد چکر لگاتے ہیں.اگرتوحید کاعقیدہ نہ اختیار کیاجائے.توقانون قدرت اورقانون شریعت دونوں کی بنیاد ہل جاتی ہے.قانون شریعت کاتعلق توواضح ہی ہے.مگرقانون قدر ت کی تما م ترقیا ت اورسائنس کی تما م تربنیاد بھی توحید پر ہی ہے.کیونکہ اگر مختلف
Page 328
خدامانے جائیں توان کے مختلف قانون ہونے چاہئیں.یاپھر کم از کم اس میں مختلف تبدیلیاں ہوتی رہنی چاہئیں.اور اگر ایساہویعنی ایک اٹل قانو ن اورایک قائم سلسلہ قانون قدرت کادنیا میں جاری نہ ہو.تو تمام علمی ترقیات یک دم بند ہوجائیں گی.کیونکہ سائنس کی ترقی اورایجادات کی وسعت کی بنیاد اسی پرہے کہ دنیا میں ایک منظم اورنہ بدلنے والاقانون جاری رہے.اگرانسان کو یہ خیال ہو کہ عالم میں کوئی نظام نہیں.یایہ کہ نظام بدلتا رہتاہے تووہ کبھی بھی قانون قدر ت کی باریکیوںکے دریافت کرنے کی طرف توجہ نہیں کرسکتا.توحید کے بعد والدین سے حسن سلوک کے ذکر میں حکمت توحید پریقین رکھنے کاحکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کاحکم دیا ہے.کیونکہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف ہی توجہ دلاتے ہیں.وہ طبعی قانون کاایک ایساظہور ہیں جوقانون شریعت کی طرف لے جاتاہے.کیونکہ وہ مبدی(پیداکرنے والی ذات)پر دلالت کرتے ہیں.والدین کے ذریعہ سے پیدائش بتاتی ہے کہ انسان اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہوگیا.اس سے پہلے کوئی اورتھا.اوراس سے پہلے کوئی اور.غرض ایک لمباسلسلہ تھا.جس سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر شہادت ملتی ہے.بغیرتناسل کے اصول کے انسان کاذہن مبداکی طرف جاہی نہیں سکتاتھا.اگریہ نظام نہ ہوتاتوانسان کواس لمبی کڑی کی طرف کبھی توجہ ہی نہ ہوتی.لیکن اس کے ساتھ ہی سلسلہ تناسل یہ بھی بتاتا ہے کہ انسانی پیدائش کی غرض اوراس کامقصد بہت بڑاہے.پس توحید کے حکم کے بعد والدین کے متعلق احسان کاحکم دیا.کیونکہ ایک احسان کی قدر دوسرے احسان کی قدر کی طرف توجہ کو پھراتی ہے.وَ بِالْوَالِدَيْنِ۠ اِحْسَانًا.اس کاعطف اَنْ پر ہے.پوراجملہ یہ ہے.اِنِ احْسِنُوابِالْوَالِدَیْنِ اِحْسَانًا.یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تویہ حکم دیا ہے کہ خداکے سواکسی کو معبود نہ بنائو.اورایک یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو.اس جملہ میں کیالطیف رنگ اختیار کیاگیا ہے.اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انسان بدلہ نہیں دے سکتا.اس لئے خدا تعالیٰ کے ذکر میں یہ بیان کیا کہ احسان توتم کرنہیں سکتے.پس ظلم سے توبچو.لیکن والدین کے احسان کابدلہ دیاجاسکتا ہے.ا س لئے ان کے بارہ میں مثبت حکم دیا.عِنْدَکَ کے لفظ میں یہ بتایاہے کہ اگروہ تمہاری کفالت میں بھی ہوں توبھی کچھ نہ کہنا.کجایہ کہ وہ الگ رہتے ہوں.اورپھر بھی تمہارے ہاتھوں تکلیف پائیں.کفالت کی خصوصیت اس لئے فرمائی.کہ ہروقت کے پاس رہنے سے اختلافات زیادہ رونما ہوتے ہیں.اورپھر یہ بھی قاعدہ ہے کہ انسان جس پر خرچ کرتاہے اس پر اپنا حق بھی سمجھنے لگتاہے.
Page 329
اُفّ.کلمہءِ ضجر ہے یعنی ناپسندید گی کاکلام.یعنی یہ کہنا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں اورنھرناپسندیدگی کوعملی جامہ پہنانے کوکہتے ہیں.یعنی نہ منہ سے نہ عمل سے ان کو دکھ دو.والدین کی خدمت کا موقعہ ملنے کے باوجود جنتی نہ بننا بد قسمتی ہے اسلام نے والدین کی خدمت کے لئے خاص ہدایات دی ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَمَنْ اَدْرَکَ اَحَدَ وَالِدَیْہِ ثُمَّ لَمْ یُغْفَرْلَہ فَاَبْعَدَہُ اللہ عَزَّوَجَلَّ رَوَاہُ اَحْمَد(مسند احمد ،مسند الکوفیین حدیث ابی من مالک.ابن کثیر زیر آیت ھذا) یعنی جس شخص کواپنے والدین میں سے کسی کی خدمت کاموقعہ ملے اورپھر بھی اس کے گناہ نہ معاف کئے جائیں تو خدااس پر لعنت کرے مطلب یہ کہ نیکی کا ایسااعلیٰ موقعہ ملنے پر بھی اگروہ خدا کافضل حاصل نہیں کرسکا.توجنت تک پہنچنے کے لئے ایسے شخص کے پاس کوئی ذریعہ نہیں.وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ اور(ان پر)رحم کرتے ہوئے ان کے لئے خاکساری کابازو جھکادے اور(ان کے لئے دعاکرتے وقت )کہاکر (کہ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًاؕ۰۰۲۵ اے )میرے رب ان پر (اسی طرح )مہربانی کر کیونکہ انہوں نے (میری)بچپن کی حالت میں میری پرورش کی تھی حلّ لُغَات.وَاخْفِض وَاخْفِضْ خَفَضَ سے امرکاصیغہ ہے.اور خَفَضَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں ضِدُّ رَفَعَہٗ.اس کو نیچا کیا.وَفِی القُرْاٰن وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَیْ تَوَاضِعْ لَہُمْ.اور قرآن مجید کی آیت وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَمیں وَاخْفِضْ کے معنے تواضع کرنے کے ہیں.خَفَضَ صَوْتَہٗ کے معنے ہیں.اَخْفَاہٗ وَغَضَّہٗ.آواز کو نیچا کیا.خَفَضَ الصَّوْتُ:لَانَ وَسَھُلَ.آواز نرم ہوگئی.(اقرب) الْجَنَاحُ.اَلْجَنَاحُ :مَایَطِیْرُ بِہِ الطَّائِرُ.پرندے کا بازو.یَدُا لْاِنْسَانِ.انسان کا ہاتھ اَلْعَضُدُ.بازو اَلْجَانِبُ جانب.اَلْکَنَفُ.پناہ.(اقرب) الذلُّ.الذلُّ اللِّیْنُ وَالسَّھُوْلَۃُ.ذُلٌّ کے معنے نرمی اور آسانی کے ہیں.وَالتَّوَاضُعُ.تواضع.اَلْاِنْقِیَادُ.فرمانبرداری.(اقرب) تفسیر.اور ان کے لئے رحمت کے ساتھ اپنے انکسار کے بازو نیچے گرا دے.اور یہ دعا کرتا رہ کہ اے
Page 330
میرے رب تو ان پر رحم کر.کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے.اس لطیف تشبیہ میں بتایا ہے کہ تیر اہاتھ ہروقت ان کی خدمت میں لگا رہنا چاہیے.والدین کے لئے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اس آیت میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ انسان بالعموم والدین کی ویسی خدمت نہیں کرسکتا.جیسی کہ ماں باپ نے اس کی بچپن میں کی تھی.اس لئے فرمایا کہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا.کہ اے خدا تُو ان پر رحم کر.تاکہ جو کسر عمل میں رہ جائے دعا سے پوری ہوجائے.ک کے معنے تشبیہ کے بھی ہوتے ہیں.ان معنوں کی رو سے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو ویسی ہی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ بچہ کو بچپن میں.والدین کے لئے یہ دعا اس لئے بھی سکھائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا اسے خود بھی اپنا فرض ادا کرنے کا خیا ل رہے گا.رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ١ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ تمہارارب جو کچھ (بھی ) تمہارے دلوں میں ہو اسے (سب سے ) بہتر جانتا ہے اگر تم نیک ہوگے تو (یاد رکھو کہ) وہ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ۠ غَفُوْرًا۰۰۲۶ باربار رجوع کرنے والوں کو بہت ہی بخشنے والا ہے.حلّ لُغَات.اَوَّابِیْنَ.اَوَّابٌ کی جمع اَوَّابُوْنَ آتی ہے.اور اَوَّابٌ آبَ سے مبالغہ کا صیغہ ہے.آبَ اِلَی اللہِ کے معنے ہیں.رَجَعَ عَنْ ذَنبِہٖ وَتَابَ اپنے گناہ سے لوٹ کر اللہ کی طرف رجوع کیا (اقرب) پس اَوَّابٌ کے معنے ہوںگے بار بار رجوع کرنے والا.تفسیر.یعنی اگر ایسی نیک نیتی اپنے دل میں پیدا کرے جو اوپر بیان ہوئی ہے تو پھر خدا تعالیٰ بھی اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے یعنی اس کے عمل میں جو کمی رہ جائے اللہ تعالیٰ اسے پوری کردیتا ہے.اس آیت کا مضمون اس حدیث سے بھی ملتاہے جو اوپر گذرچکی ہے اور جس کا یہ مضمون ہے کہ والدین کی خدمت کا موقع پاکر بھی جس کے گناہ نہ بخشے جائیں اس پر لعنت ہوکیونکہ اس آیت کا مضمون یہی بتاتا ہے کہ جو صالح ہوگا یعنے اوپر کے احکام کے مطابق عمل کرے گا توا س سے خدا تعالیٰ مغفرت کا معاملہ کرے گا.
Page 331
وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ وَ لَا اور قرابت والے کو اور مسکین کو اور (مسافر)راہروکو اس کاحق دے تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا۰۰۲۷ اور اسراف کسی رنگ میں(بھی )نہ کر.حلّ لُغَات.لَا تُبَذّرْ.لَا تُبَذِّرْ بَذَّرَسے نہی مخاطب کا صیغہ ہے.اور بَذَّرَالْمَالَ کے معنے ہیں فَرَّقَہٗ اِسْرَافًا(اقرب).مال کے خرچ کرنے میں فضول خرچی سے کام لیا.پس لاتُبَذِّرْ کے معنے ہوںگے.توا سراف نہ کر.تفسیر.ہر شخص کے مال میں رشتہ داروں اور مساکین کے حق ہونے کی دلیل اس آیت میں بتا یا گیا ہے کہ ہر شخص کے مال میں رشتہ داروں.مساکین اور مسافروں کا حق ہے رشتے دار انسان کی کمائی میں کئی طرح مدد کا موجب ہوتے ہیں.اس لئے اس کے مال میں ان سب کا حق ہوتا ہے مثلاً والدین نے ایک بیٹے کو پڑھا دیا.اور وہ کسی اعلیٰ عہدہ پر پہنچ گیا اور باقی بھا ئی علم سے محروم رہے تو اس عہدہ دار کے مال میں باقی بھائیوں کا بھی حق ہے کیونکہ جس روپے سے اس کو تعلیم دلائی گئی تھی اس میں ان سب کا حق تھا.مساکین اور ابن السبیل کابھی اللہ تعالیٰ نے حق قرار دیا ہے اور دوسری جگہ کھول کر بھی بتایا ہےوَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمِ (الذاریات:۲۰)کہ انسان کے اموال میں سائل وغیرہ کا بھی حق ہوتاہے.مساکین کا حق قرار دینے کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ دنیا میں امیر غریب بدلتے رہتے ہیں.جو آج غریب ہیں کبھی امیر تھے اور جو آج امیر ہیںکبھی غریب تھے اور اس وقت کے امیروں نے ان سے حسن سلوک کیا تھا.پس ساری دنیا کواگر مجموعی نگاہ سے دیکھا جائے تو کسی کا مال اس کا خالص مال نہیں بلکہ اس میں دوسروں کے حقوق شامل ہیں.دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کی سب اشیا ء اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کےلئے بحیثیت جماعت پیدا کی ہیں نہ کہ زید یا بکر کے لئے.پس اگر زید یا بکر کسی وجہ سے زیا دہ مالدار ہوگئے ہوں تو اس سے ان باقی لوگوں کا حق باطل نہیں ہوجاتا.جو دنیا کی چیزوں کی ملکیت میں زید اور بکر کے ساتھ برابر کے شریک ہیں.بےشک بوجہ خاص محنت کے زید اور بکر کا زائد حق اسلام تسلیم کرتاہے لیکن ان کو مالک بلاشرکت غیر نہیں تسلیم کرتا.ہر شخص کے مال میں مسافروں کے حق ہونے کی وجہ مسافروں کا حق اس طرح کہ جب یہ دوسری جگہ
Page 332
کی طرف جاتاہے تو وہ اس سے حسنِ سلوک کرتے ہیں.پس دوسرے مقام کے مسافر کی خدمت کرنا اس کافرض ہے تاحق ضیافت ادا ہوتارہے.ابن السبیل کے حق کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بستی میں جائو تو تین دن تک کی ضیافت کا تم کو حق ہے.صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اگر بستی والے نہ دیں.فرمایا چھین کر بھی لے سکتے ہو.(ابوداؤد کتاب الاطعمۃ باب ماجاء فی الضیافۃ) یہ حکم اس وقت کے لئے ہے جب اسلامی تمدن جاری ہوکیونکہ ان ایام میں دوسرے لوگ اس سے ضیافت کا حق لے سکیں گے.اس حکم کو اگر دنیا میں جاری کیا جائے تو بہت سی خرابیاں جو ہوٹلوں اور سرائوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں دنیا سے دور ہوجائیں اور غرباء کے لئے بھی دنیا کا سفر جو اعلیٰ تربیت کا ایک ذریعہ ہے آسان ہوجائے گا مگر افسوس کہ خود مسلمانوں نے بھی اس حکم کو بھلادیا ہے.مسافروں سے حسنِ سلوک کا یہ عام حکم دنیا سے بہت سے فتنے مٹانے کا موجب ہے.کیونکہ لڑائی جھگڑا منافرت سے پیدا ہوتاہے.اگر اس طرح مہمان نوازی کا رواج ہو تو منافرت دور ہوجائے.اور گائوں اور ملکوں کے جھگڑے مٹ جائیں.وہ لوگ جو کسی دوسرے ملک کی مہمان نوازی سے فائدہ اٹھا چکے ہوں کبھی بھی جلدی سے ان کے خلاف لڑنے پر آمادہ نہ ہوںگے سوائے خبیث ارواح کے جو نسبتاً تھوڑی ہوتی ہیں.نیز اس حکم سے گائوں اور قصبوں کے نظام کی بنیاد بھی پڑتی ہے کیونکہ مہمان نوازی سارے گائوں پر واجب کی گئی ہے.پس اس حکم کے پورا کرنے کے لئے ہرگائوں والے ایک ایسے نظام کی پابندی پر مجبور ہوںگے جس کے ماتحت سارا گائوں مہمانوں کی خدمت کرسکے اور یہ نظام ان کے دوسرے کاموں میںبھی مفید ثابت ہو گا.لَاتُبَذِّرْ.پھر فرمایا کہ اوپر کے احکام میں مال کو خرچ کرنے کی جو نصیحت کی گئی ہے.اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ ما ل کو لٹا دینا چاہیے ہم نے انہی اخراجات کا حکم دیا ہے جو ضروری ہیں بے فائدہ مال لُٹانے کا حکم نہیں دیا.فضول خرچی کی تشریح ابن مسعود کا قول ہے اَلتَّبْذِیْرُ.الْاِنْفَاقُ فِیْ غَیْرِ حَقٍّ (ابن کثیر زیر آیت ھذا).یعنی ناجائز خرچ کو تبذیر کہتے ہیں.پس اس حکم میں دینی انفاق شامل نہیں.دین کی کسی ضرورت کےلئے اگر کوئی اپنا سارا مال بھی خدا کی راہ میں دےدے تو وہ مبذرنہ ہوگا.کیونکہ اس نے بے جا خرچ نہیں کیا.قرآن مجید نے فضول خرچی کی دوسری جگہ تشریح یوں فرمائی ہے.وَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَ لَمْ يَقْتُرُوْا وَ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا(الفرقان:۶۸)کہ نہ تو اسراف کرناچاہیے اورنہ کنجوسی سے کام لیناچاہیے مگرمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے.
Page 333
اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ۠ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ١ؕ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ اسراف کرنے والے لوگ یقیناً شیطانوں کے بھا ئی ہوتے ہیںاور شیطان لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا۰۰۲۸ اپنے رب کا بہت ہی ناشکر گذار ہے.تفسیر.فرمایاکہ اگر تم ایساکروگے توناشکری ہوگی.ہم نے تمہیں یہ مال اسی لئے دیاہے کہ تم اس کو برمحل خرچ کرو اب جو تم اس کو یوں پھینکو گے توا س کے یہ معنے ہوں گے کہ مال کے ساتھ جوذمہ واریاں اللہ تعالیٰ عائد فرماتا ہے ان سے بچناچاہتے ہو اوریہ ایک گنا ہ ہے.رہبانیت کا ردّ اس آیت میں کس لطیف طریق سے رہبانیت وغیر ہ کارد کیا ہے.رہبانیت کیا ہے ذمہ واریوں سے بچنے کاایک ذریعہ ہے اوریہ فعل نیکی نہیں کہلا سکتا بلکہ ایک کھلی بدی ہے اورشیطانی فعل ہے.اللہ تعالیٰ کے احسان کی ناقد ری ہے.وَ اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا اوراگر تواپنے رب کی طرف سے کسی رحمت کی جستجومیں جس کی توامید رکھتا ہوان سے اعراض کرے تو(پھر بھی فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا۰۰۲۹ انہیں سختی سے رد نہ کر بلکہ)انہیں کوئی نرم بات کہہ دو.حلّ لُغَات.مَیْسُوْرًا مَیْسُوْرًاکے معنے ہیں مَایُسِّرُ خِلَافُ الْمَعْسُوْرِوَھُوَ مَصْدَرٌ عَلٰی مَفْعُولٍ بِمَعْنَی الْیُسْرِ.مَیْسُوْرٌ اسم مفعول بھی ہے اورمصدر بھی اوراس کے معنی ہیں و ہ چیز جوآسان کی گئی ہویاآسانی.السَّہْلُ.سہولت.وَمِنْہُ فَقُلْ لَہُمْ قَوْلًا مَّیْسُوْرًا اورفَقُلْ لَہُمْ قَوْلًامَّیْسُوْرًا میں قَوْلٌ مَیْسُوْرٌکے معنی نرم بات کے ہیں.(اقرب) تفسیر.اس آیت کے دومعنے ہیں (۱)جب تم اقرباء مساکین وغیر ہ سے اعراض کرویعنی ان کی مدد نہ
Page 334
کرسکو.توا س بات کی ضرور نیت کرلو کہ جب اللہ تعالیٰ دے گاتوضرور دوں گا.اورساتھ ہی تم ان کویہ بات نرمی سے سمجھا دوکہ توفیق ملنے پر تمہاری ضرورمدد کروں گا.(۲)دوسرے معنی یہ ہیں کہ اگراللہ تعالیٰ کے فضل کی امید میں یعنی یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرادینا ان کی دینی یااخلاقی حالت بگاڑ دے گاغرباء کی مددسے اعراض کرے توتُوان کو نرمی سے سمجھا دے گویا اعراض ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ ہوناچاہیے نہ کہ بخل کی وجہ سے.مثلاً کوئی ہٹاکٹاآد می سوال کرے اورجس سے سوال کیا جائے وہ اس نیت سے اس کے سوال کو پورانہ کرے کہ قوم میں سوال کی عادت نہ پیداہوجائے تویہ جائز ہے.مگر اس انکار کاباعث بخل اورکنجوسی نہ ہو.سائل سے حسن سلوک کی تاکید اسی طرح مثلاً سائل مسر ف ہویا نشہ شراب افیون کی بد عادت میں مبتلاہواس کی مالی مدد سے اگریہ اس وجہ سے باز رہتا ہے کہ میں نے اس کی امداد کی تو اس کی صحت خراب ہوگی ملک میں بدی ترقی کرے گی اورنہ دینے سے اس کی نشہ کی عادت چھوٹے گی اورملک کو بھی فائدہ پہنچے گاتویہ شخص گناہ گار نہ ہوگا.بلکہ نیکی کامرتکب.حدیث میں آتاہے بعض ایسے سائلوںکے آنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے یا انہیں سمجھادیتے تھے.(نسائی کتاب الزکوٰۃ باب مسئلۃ القوی المکتسب) وَ لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ اورتونہ (توبخل سے )اپنے ہاتھ کو باند ھ کراپنی گردن میں ڈال لے.اورنہ(اسراف میں پڑ کر)اسے بالکل کھول الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا۰۰۳۰ دے.ورنہ (یاتو)توملامت کا نشانہ بن کر (اوریاپھر )تھک کربیٹھ جائے گا.حلّ لُغَات.مَغْلُوْلَۃً.مَغْلُوْلَۃً غَلَّ سے اسم مفعول مؤنث کاصیغہ ہے.اورغَلَّ فُلَانًا کے معنے ہیں : وَضَعَ فِی یَدِہٖ اَوْعُنُقِہٖ الْغُلَّ.اس کے ہاتھوں یاگردن میں طوق ڈالا (اقرب)پس لَاتَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُوْلَۃً کے معنے ہوں گےتو اپنے ہاتھو ں کو باندھ کر اپنی گردن میں نہ ڈال لے.مَحْسُوْرًا.مَحْسُوْرًا حَسَرَ سے اسم مفعول ہے اورحَسَرَالشَّیْءَ کے معنے ہیں.کَشَفَہُ.کسی چیز سے پردہ کو ہٹایا.حَسَرَالْغُصْنَ :قَشَرَہُ.ٹہنی کے چھلکے کو اتارا.حَسَرَ الْبَعِیْرَ: سَاقَہُ حَتّٰی اَعْیَاہُ.اونٹ کو اتنا چلا یاکہ وہ تھک گیا.حَسَرَ الْبَیْتَ کَـنَسَہُ.گھر میں جھاڑودیا.(اقرب) مَحْسُوْرٌ کے معنے ہوں گے.جھاڑو دیا ہوا.
Page 335
ننگا کیاہوا.تھکایا ہوا.تفسیر.اس آیت میں بتایا ہے کہ خرچ کے متعلق اس اصل کو مدنظر رکھو کہ نہ توہاتھ گردن سے بندھا رہے.یعنی ضرورت کے وقت بھی خرچ کرنے سے دریغ ہو اورنہ ہاتھ ہروقت مال لٹانے کےلئے دراز رہے بلکہ چاہیے کہ تم ضرورت کے مطابق خرچ کروتابے ضرورت خرچ تم کو اس وقت کی نیکی سے محروم نہ کردے جبکہ خرچ کرنے کی کوئی صحیح ضرورت پیداہوگئی ہو.بے ضرورت خرچ کر نے کے نقصان بے ضرورت خرچ کرنے کے دونقصان بتائے ہیں ایک تویہ کہ جوشخص بے ضرورت خرچ کرتاہے ضرورت کے وقت جبکہ اس کے دوسرے ساتھی خرچ کررہے ہوتے ہیں.یہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے اورقوم اسے ملامت کرتی ہے کہ آج ملک یاقوم کوضرورت تھی اورآج تم خاموش بیٹھے ہو اوردوسرانقصان یہ کہ اس طرح انسان محسوریعنی ننگاہو جاتا ہے یعنی جب ضرورت کے وقت یہ کام نہیں آسکتا توقوم پر اس کاعیب ظاہرہوجاتا ہے اوروہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے اپنے مال کی حفاظت نہیں کرسکااوریہ بھی کہ یہ دوسروں کا محتاج ہوجاتا ہے.حَسَرَ الْبَیْتَ کے معنے گھر میںجھاڑو دے کراسے صا ف کردیا کے بھی ہیں.پس محسور کے معنے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ تواس حالت میں ہو جائے کہ گویا کہ تیرے گھر میں جھاڑ و مل گیا.اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ١ؕ اِنَّهٗ كَانَ تیرارب یقیناً جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو وسیع کردیتا ہے اور(جس کے لئے چاہتا ہے )تنگ کرتا ہے وہ یقیناً بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًاؒ۰۰۳۱ اپنے بندوں (کے حالات )کوجاننے والا (اور)دیکھنے والا ہے.تفسیر.اس میں یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ کسی کو فراخی دیتا ہے اور کسی کے رزق میں تنگی کرتا ہے تایہ دیکھے کہ جومالدارہیں وہ غرباء کی کس طرح مددکرتے ہیں.پس اگرتم دنیاکے اموال کی اس نیت سے حفاظت کرو کہ ان کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کے بندوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرسکو تویہ ایک بہت بڑی نیکی ہو گی.
Page 336
قرآن کریم کی کیا ہی معجزانہ شان ہے کہ ابھی مسلمان مکہ میں تکلیف اٹھارہے تھے کہ اس نے مسلمانوں کے لئے وہ احکام بیان کرنے شروع کردئے جو ان کے لئے ترقی کے زمانہ میں ضروری تھے.کیااس کے سواجواپنی بات کے پوراکرنے پر کامل طورپر قادر ہو کوئی دوسرااس طریق کو اختیار کرسکتا ہے.اگر یہ کلام انسان کاہوتا تو مکہ میں اوران حالات میں جن میں سے مسلمان گذر رہے تھے.یہ الفاظ نکالتے وقت اس کاحلق خشک ہوجاتا اورالفاظ حلق میں ہی اٹک کر رہ جاتے.وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ١ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اور تم مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کوقتل مت کرو.انہیں (بھی)ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی (ہم ہی دیتے اِيَّاكُمْ١ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا۰۰۳۲ ہیں)انہیں قتل کرنا یقیناً(بہت) بڑی خطاہے.حلّ لُغَات.اِمْلَاقٌ : اِمْلَاقٌ اَمْلَقَسے مصدر ہے اوراَمْلَقَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں اَنْفَقَ مَالَہٗ حَتّٰی اِفْتَقَرَ.اتنا مال خرچ کیا کہ پھر محتاج و مفلس ہوگیا (اقرب)پس اِمْلَاقٍ کے معنے ہوں گے مال ضائع ہوکر محتاج و مفلس ہوجا نا.اَلْخِطْأَ.اَلذَّنْبُ.قصور.مَاتَعَمَّدَ مِنْہُ.جان بوجھ کر کی ہوئی غلطی (اقرب) تفسیر.پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایاتھا کہ احسان تولوگوں پر کرو لیکن یہ خیال رکھ لو کہ تمہارااحسان کرنااس رنگ پر نہ ہو کہ اس کے نتیجہ میں لوگ بدیوں میں بڑھ جائیں یاتم خود بدی میں پڑ جائو.آیت لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ الخ کا مطلب اب فرماتا ہے کہ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ یعنی اس خوف سے کہ اولادپر روپیہ خرچ ہوگاان کو ہلا ک نہ کرو یہ حکم لڑکیوں کے قتل کرنے کے متعلق نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم میں لڑکیوں کے قتل کی کسی جگہ بھی یہ وجہ بیان نہیں فرمائی کہ لوگ خرچ کے ڈر سے ان کو قتل کردیتے ہیں.بلکہ یہ وجہ بتائی ہے کہ ان کی پیدائش کو اپنے لئے ذلت کاموجب سمجھتے ہیں اس لئے ان کو مار ڈالتے ہیں اسی طرح اس آیت کے یہ معنے بھی نہیں ہوسکتے ہیں کہ بوجہ غربت اورتنگی کے اولا دکو قتل نہ کرو.کیونکہ املاق کے معنی غربت اورتنگی کے
Page 337
نہیں ہیں.بلکہ اس کے معنے مال کے خرچ ہونے کے ہیں.اورآیت کے یہ معنے ہیں کہ ا س ڈرسے نہ ماروکہ روپیہ خرچ ہوگا.اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ا س ڈر سے کہ روپیہ خرچ نہ ہو کوئی اولاد کو قتل کرتابھی ہے ؟سوجہاںتک دنیا کا تجربہ ہے اس قسم کے واقعات صحیح الدما غ لوگوں میں توملتے نہیں.بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس روپیہ نہیں ہوتا وہ بھی اولا دکو نہیں مارتے.پس معلوم ہواکہ ا س قتل کاکوئی اورمفہوم ہے.اورہمیں انسانوں میں اس جرم کی تلاش کرنی چاہیے.سوجب ہم مختلف انسانوں کی حالتوں کو دیکھتے ہیں توہمیں معلو م ہوتا ہے کہ بعض لوگ بخل کی وجہ سے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے.پوری غذا نہیں دیتے یاایسی غذانہیں دیتے جو نشوونما کے لئے ضروری ہو ایسے بخیل توبے شک فاترالعقلو ں میں ہی ملتے ہیں جوزہر سے یاگلا گھونٹ کراپنی اولاد کو اس خوف سے مارتے ہوں کہ ان پرہمار ی دولت خرچ ہوگی.مگرایسے بخیل عام صحیح الدماغ لوگوں میں کثرت سے ملتے ہیں کہ پاس روپیہ ہے لیکن بچوں کو بخل کی و جہ سے اچھی غذا نہیں دیتے.لباس مناسب نہیں دیتے حتیٰ کہ بعض دفعہ وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے بیمار ہوجاتے ہیں.بعض دفعہ لباس کی کمی کی وجہ سے نمونیہ وغیر ہ کاشکار ہوجاتے ہیں.اس قسم کے لوگ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملتے ہیں اورہرملک میں ملتے ہیں.اسی طرح قتل سے مراد اخلاقی اور روحانی قتل بھی ہوسکتا ہے کہ روپیہ کے خرچ کے ڈرسے اچھی تعلیم نہیں دلاتے اورگویا بچہ کی اخلاقی یاروحانی موت کاموجب ہوجاتے ہیں.ا س آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کرتاہے کہ اس فعل سے اجتناب کریںا ورو ہ اخراجات جو بچوں کی صحت اوراخلاق کی درستی کے لئے ضروری ہیں.ان سے کبھی دریغ نہ کیا کریں.اورقتل کالفظ اس لئے استعمال کیا ہے کہ اولاد کو قتل کرنے سے انسان فطرتاً تنفر کرتا ہے پس اس لفظ کے استعمال سے اس کی توجہ اس طرف پھیرائی ہے.کہ تم کسی صورت میں بھی اولاد کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے پر تیار نہیں ہوتے لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک اور قسم کے قتل کے تم مرتکب ہورہے ہو.یعنی اولادکی خوراک اورلباس کاخیال نہیں رکھتے اوران کی صحتوں کو برباد کردیتے ہو.یاان کی تربیت کاخیال نہیں رکھتے اوران کے اخلاق کو برباد کردیتے ہو.لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ میں قتل کے لفظ کے استعمال کی وجہ قتل کالفظ استعمال کرنے کی میرے نزدیک یہ بھی وجہ ہے کہ اگر صرف یوں کہاجاتا کہ اولاد پر ضرو رخرچ کیا کرو.توان الفاظ میں ان بالواسطہ اثرات کی طرف اشارہ نہ ہوتا جو اولاد کی زندگی پر پڑتے ہیں.لیکن ان الفاظ کے استعمال نے تمام بالواسطہ تاثیرات کوبھی اپنے اندر شامل کرلیا ہے.مثلاً بیوی کی خوراک اورمناسب لباس کاخیال نہ رکھنا.یادودھ پلانے یاایام حمل میں اس پر کام
Page 338
کابہت بوجھ ڈال دینا.یہ سب امورہیں جن سے اولاد پربرااثر پڑتا ہے.اوریاتوبچے ضائع ہوجاتے ہیں یاان کی صحتیں کمزورہوجاتی ہیں.لَا تَقْتُلُوْۤا کے الفاظ میں ان سب امو ر کی مناہی آجاتی ہے اوریہ غرض دوسرے الفاظ سے پوری نہ ہوسکتی تھی.اس آیت کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں جوبعض صوفیاء کرتے ہیں.کہ اولاد کی پیدائش کو صرف ا س خطرہ سے روکنا منع ہے کہ اگراولاد زیادہ ہوجائے گی توپھر کھائے گی کہاں سے.اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اولاد کی پیدائش بند کرنا قتل اولاد کے حکم میں ہے.اورقتل اولاد ہرحال میں منع ہے اوربراہے.تومعنے یہ ہوئے کہ املاق کی وجہ سے قتل اولاد (یعنی اس کی پیدائش کو روکنا )منعہے.البتہ بعض اورصورتوں میں جائز بھی ہوسکتا ہے مثلاً عورت بیمار ہو اس وقت جائز ہوگاکہ اولادپیداکرنابند کردے.کیونکہ جس چیز کی وجہ سے قتل اولاد کوروکا گیا ہے.وہ غیر محسوس ہے ایسی وجہ کی بناء پر اولاد کی پیدائش کوروکنا ناجائز ہے لیکن کسی محسوس اورمشاہد نقصا ن کی وجہ سے اولاد کی پیدائش کو روکنا منع نہیں.علاوہ پیدائش میں روک ڈالنے کے جو بچہ بن چکاہو بعض حالات میں اس کامارنابھی جائز ہوتاہے مثلاً کسی حاملہ عورت کے متعلق زچگی کے وقت یہ شبہ ہو کہ اگر بچہ کو طبعی طور پر پیدا ہونے دیاگیا تووالد ہ فوت ہوجائے گی اس صورت میں بچہ کوضائع کردیناجائزہے کیونکہ بچہ کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ وہ مردہ پیدا ہوگایا زندہ.یازندہ رہے گایا نہیں.مگر ماں سوسائٹی کا ایک مفید وجود ہے اس لئے وہمی نقصان سے حقیقی نقصا ن کو زیادہ اہمیت دی جائے گی اوربچہ کو تلف کردیاجائے گا.لَا تَقْتُلُوْۤا کے بعد خَشْيَةَ اِمْلَاقٍلگانے کی وجہ غرض لَا تَقْتُلُوْۤا کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ کی شر ط لگاکر قرآن کریم نے اولاد کی تربیت ،اس کی پرورش ،ماں کی پرورش اوراس کی زندگی کی قیمت کے متعلق ایک وسیع مضمون بیان کیا ہے اورایسے مختصرالفاظ میں کہ اس کی مثال دوسری کتاب میں نہیں مل سکتی بلکہ حق یہ ہے کہ یہ مضمون ایسااچھوتاہے کہ دوسری کسی مذہبی کتاب نے اسے چھواتک نہیں.خِطْاً کے معنے اس آیت میں جو خِطْأً کا لفظ استعمال کیا گیاہے گواس کا مادہ اورخَطَأً کاماد ہ ایک ہی ہے لیکن خِطْأً جو خ کی زیر کے ساتھ ہے اس کے معنوں اورخَطَأً جس میں خ پر زبر ہے اس کے معنوں میں فرق کیا جاتا ہے.خِطْأًکے معنے اَلْاِثْمُ مَاتُعَمِّدَ مِنْہُ کے ہیں.اور خَطَأً کے معنے مَالَمْ یَتَعَمَّدْ مِنْہُ اَوْ تَعَمَّدَ کے ہیں.یعنی اگر خ پر فتح یعنی زبر ہوتو دیدہ دانستہ گناہ اورنادانستہ قصور دونوں معنوں میں مستعمل ہوگا.اوراگر خ کے نیچے کسرہ
Page 339
یعنی زیر ہو تو اس سے مراد صر ف وہ گنا ہو گا.جس میں اراد ہ پایاجائے اس لفظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اولاد کاقتل ایک ایسا جرم ہے کہ جس کوفطرت بھی رد کرتی ہے یعنی جس کے احساسات طبعی مرچکے ہوں وہی ایسافعل کرسکتا ہے.دوسرانہیں کرسکتا.اِنَّہُ کَانَ خِطْأً کَبِیْرًا کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں وہ قتل مراد نہیں جو زہر یاآلہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ قتل کثر ت سے پایا جاتا ہے مگر اپنے ہاتھوں بچوں کاقتل ہرگز کسی ملک میں بھی ایسے رنگ میں نہیں پایاجاتا کہ اسے قومی جرم قراردیا جائے اس امر کاثبوت کہ یہ عام قتل سے جداقسم کاقتل ہے یہ بھی ہے کہ قتل کے خلاف حکم آگے چل کر بیان کیا گیا ہے.اس میں بچوں کاقتل بھی شامل ہے پس ظاہر ہے کہ اس جگہ قتل سے مراد کچھ اورہے.اس آیت میں نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ فرماکر اس امر پر زور دیا ہے کہ انسان کے رزق میں اس کی اولاد کا رزق شامل ہے پس اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے اسی وجہ سے نَرْزُقُھُمْ کو پہلے رکھا اورباپ کے رزق کوبعد میں بیا ن کیا ہے.وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً١ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا۰۰۳۳ اورزناکے قریب (بھی )نہ جائو وہ یقیناً ایک کھلی بے حیائی اوربہت براراستہ ہے.حلّ لُغَات.فَاحِشَۃ.فَاحِشَۃٌکے معنے ہیں مَایَشْتَدُّ قُبْحُہٗ مِنَ الذَّنُوْبِ.ہروہ غلطی جو بہت بُری ہو.وَقِیْلَ کُلُّ مَانَھَی اللہُ عَنْہٗ.ہروہ بات جس سے اللہ نے روکاہے.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں زناسے بچنے کاحکم قتل اولاد کے ذکر کے بعد دیا ہے.اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ زناسے بھی اولاد کاقتل ہوتا ہے.کیونکہ اول تو حرام کی اولادکو عام طورپر ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.دوسرے اگر ضائع نہ بھی ہو تب بھی اس کی تربیت اورپرورش میں مرد کھل کرحصہ نہیں لے سکتا.اوروہ اولاد بالعموم بغیر والی وارث کے رہ کرتباہ ہوجاتی ہے.وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى میں لفظ قرب کے استعمال میں حکمت لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى کے الفاظ استعمال کرکے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مواقع زناپیداہی نہ ہونے دو.یعنی نامحرم عورتوں سے الگ نہ ملو.ان سے زیادہ خَلاملا نہ رکھو وغیرہ وغیرہ.قرآن کریم کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ نہ صرف گناہ سے روکتاہے بلکہ گناہ سے بچنے کے ذرائع
Page 340
بھی بتاتاہے اورایسی ہی تعلیم بنی نوع انسان کی حفاظت کرسکتی ہے.جوکتاب گناہ سے بچنے کے ذرائع نہیں بتاتی وہ انسان کو ایک پریشانی میں مبتلاکردیتی ہے.اطمینان وہی کتاب پیداکرسکتی ہے جوکسی بات سے منع کرنے کے ساتھ ہی اس سے بچنے کے ذرائع بھی بتادے تاانسان کو تسلی ہو کہ میں اس حکم پرعمل کرسکوں گا.انجیل کہتی ہے کہ توکسی عورت کو بد نظری سے نہ دیکھ.لیکن قرآن کہتاہے کہ توکسی نامحرم عورت کی طرف نظر اٹھا کرہی نہ دیکھ.کیونکہ وہ کشش جو انسان کے دل میں لغزش پیداکرتی ہے.جب اس کے لئے راستہ کھول دیاجائے توحفاظت ناممکن نہیں تونہایت مشکل ضرور ہوجاتی ہے.اس حکمت کے ماتحت اس جگہ فرمایا ہے کہ تم گناہ کے مقام سے اتنی دور کھڑے رہو.کہ جہاں سے تم بدی کامقابلہ کرسکو.بعض نے کہا ہے کہ یہ توبزدلی ہے.مگریہ بزدلی نہیں یہ تواحتیاط ہے اوراحتیاط کو کوئی عقلمند بزدلی نہیں کہتا.ظاہر ہے کہ انسان دوہی قسم کے ہوسکتے ہیں.اول وہ جو گناہ کے پاس جاکربھی بچ سکتاہے.ایسے شخص کو گناہ کے مقام سے دور رہنے کی اس لئے تاکید کی.کہ گویہ توبچ سکتا ہے مگرممکن ہے.کہ اس کی طرف دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ا س مقام تک چلے جائیں.اوراپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ میں مبتلاہوجائیں.پس ایسے شخص کولوگوں کے لئے ٹھوکر کاموجب نہ بننا چاہیے.دوسری قسم کے وہ لو گ ہیں جوگناہ کے مواقع پیدا ہونے کی صورت میں اس سے بچ ہی نہیں سکتے.ان کواس سے قریب بھی نہ جانے دینے کی حکمت تو ظاہرہی ہے.پس خواہ انسان گناہ کے قریب ہو کر بچ سکتاہو.خو اہ نہ بچ سکتاہو.دونوں صورتوں میں اس کو گناہ کے قریب تک بھی نہیں جاناچاہیے.یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس مقا م کی طرف جانے میں کوئی خاص فائدہ مدنظر ہواس کی طرف نہ جانابزدلی کہلاسکتاہے.مگر جس جگہ کی طرف جانا یانہ جاناکوئی خاص فائدہ نہ رکھتاہو اس سے الگ رہناہرگزبزدلی نہیں کہلاسکتا.سَآءَ سَبِيْلًا کے الفاظ میں زنا کے نقصانات کی طرف اشارہ سَآءَ سَبِيْلًا ان الفاظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ علاوہ اخلاقی گناہ ہونے کے زنامیں اوربھی بہت سے نقصانات ہیں.جوانسان شادی کرتا ہے وہ ضرور احتیاط کرلیتا ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرے جس کی صحت اچھی ہو.اسے کوئی متعدی مرض نہ ہو.عادات و اخلاق اچھے ہوں.اسی طرح لڑکی کے رشتہ دار لڑکے کے متعلق سوچ سمجھ لیتے ہیں.مگرزنا میں یہ احتیاط نہیں ہوسکتی.کیونکہ زناہوتاہی شہوانی جذبات کے جوش میں آجانے کی صورت میں ہے اوراس وقت انسان کسی قسم کی احتیاط نہیں کرسکتا جس کانتیجہ کئی قسم کی امراض یامالی تباہی کی صورت میں نکلتاہے پس فرمایا شہوانی تقاضوں کے پوراکرنے کایہ
Page 341
راستہ نہایت خطرناک ہے.یہ امر روزانہ تجربہ میں آرہا ہے کہ گوبیوی سے جو تعلق خاوند پیداکرتاہے اسی قسم کاتعلق زانی ،زانیہ سے کرتاہے.لیکن باوجوداس کے زناکے نتیجہ میں جس قسم کی بیماریاں پیداہوتی ہیں وہ بیوی کی صورت میں نہیں پیداہوتیں یابہت کم پیداہوتی ہیں.دنیا میں جس قدر لوگ آتشک یاسوزاک کی مرضوں میں مبتلاہوتے ہیں ان میں سے کس قدربیویوں سے اس مرض کوقبول کرتے ہیں ؟ شاید سو میں سے ایک بھی نہیں.بقیہ ننانوے فی صدی یااس سے زیادہ حصہ ان مریضوں کازناسے مرض کوحاصل کرتا ہے.اورجو مرض میاں یا بیوی کوایک دوسرے سے لگتی ہے وہ بھی درحقیقت کسی پہلے زناکے نتیجہ میں ہوتی ہے پس سَآءَ سَبِيْلًا کہہ کر ایک زبردست سچائی کی طرف انسان کو توجہ دلائی ہے جو ہے توہر اک کے سامنے لیکن اس کی طرف توجہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے.وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ١ؕ وَ مَنْ اورجس جان کو (مارنا)اللہ (تعالیٰ)نے حرام ٹھہرایا ہے اسے (شرعی )حق کے سواقتل نہ کرو اورجوشخص مظلوم ماراجائے قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي اس کے وارث کو ہم نے (قصاص کا)اختیار دیا ہے.پس (اس کے لئے یہ ہدایت ہے کہ)وہ (قاتل کو)قتل کرنے الْقَتْلِ١ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا۰۰۳۴ میں (ہماری مقررکردہ)حدسے آگے نہ بڑھے (اگروہ حد کے اندررہے گا تو)یقیناً(ہماری)مدداس کے شامل حال ہوگی حلّ لُغَات.سُلْطَان :سُلْطَانٌکے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر۱۲.السُّلْطانُ:اَلْـحُجَّۃُ.سلطان کے معنے ہیں دلیل.اَلتَّسَلُّطُ.قبضہ وَقُدْرَۃُ الْمَلِکِ.بادشاہ کی طاقت.(اقرب) لَایُسْرِفُ لَا یُسْرِفْ اَسْرَف سے نہی غائب کاصیغہ ہے اوراَسْرَفَ فِیْ کَذَاکے معنے ہیں.جَاوَزَ الْحَدَّفِیْہِ وَ اَفْرَطَ.حدسے تجاوز کرگیا.(اقرب)پس فَلَایُسْرِفْ فِّی الْقَتْلِ کے معنے ہوں گے کہ وہ قتل کرنے میں مقررہ حد سے آگے نہ بڑھے.
Page 342
تفسیر.بغیر حق کسی کو قتل کرنا منع ہے اوپرکی دوآیتوں میں قتل کے دونوں مخفی ذرائع بیان کئے تھے.اب کھلے قتل کے بارہ میں حکم بیان فرمایاگیاہے.چنانچہ فرماتا ہے کہ کسی جان کو جس کے قتل کو خدا تعالیٰ نے حرام کیا ہے قتل نہ کرنا چاہیے.بِالْحَقِّ اس لئے فرمایا کہ نفس ہراس چیز کو کہتے ہیں جوسانس لیتی ہو اوراس لئے سب جاندار اس میں شامل ہیں.بلکہ آج کل کی سائنس کی تحقیق کے روسے تونباتات کے بارہ میں بھی سانس کالیناثابت ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Plant).پس نفس کے ساتھ مَاحَرَّمَ اللّٰہُ اِلَّا بِالْحَقِّ رکھ دیا.کیونکہ دوسری چیزوں کاقتل اپنی ذات میں حرام نہیں گوبعض وجوہات سے حرا م ہو جاتا ہے مثلاً حرم شریف میں کسی جانورکو قتل نہ کرنا چاہیے.اسی طرح اگر کوئی جانور کسی دوسرے کی ملکیت میں ہو تواس کوبھی قتل کرنا حرام ہے.اسی طرح ذبح کے طریق کے سواجو حلال جانوروں کے لئے جائز ہے اَوربعض طریقوں سے جانوروںکاقتل بھی ناجائزہے.پس اِلَّا بِالحقِّ کہہ کر ایک توانسا ن کو اس حکم کے لئے مخصوص کردیا.دوسرے انسانوں میں سے ان کو حکم سے باہر نکال دیا.جن کابعض اسبا ب کے ماتحت مارناجائزہومثلاً قاتل یا جولوگ دوسرے کو قتل کرنے کے لئے حملہ آورہوں وغیرہ وغیر ہ.حق کی تشریح بِالْحَقِّ کے لفظ سے اس طرف بھی اشار ہ کیا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ملے اس وقت قتل جائز ہے.گویا نہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اوراجازت بھی اسی کی طرف سےہونی چاہیے.ا س شرط سے مواقع جنگ کو محدود کردیاگیاہے.اسی طرح حکومت کے اختیارات جان لینے کے متعلق محدود کردئے گئے ہیں.اس شرط کی وجہ سے اگر کوئی دایہ یہ کہے کہ چونکہ بچہ کی والدہ نے کہا تھا کہ بچہ کو مارڈال اس لئے میں نے مار ڈالا یاکوئی حاکم کسی کو جبراً مروادے تووہ جرم سے بری نہیں سمجھے جائیں گے.کیونکہ قتل اسی صورت میں جائز ہے جبکہ اس جان کو پیداکرنے والے کی طرف سے قتل کرنے کا حق کسی کو عطا ہوا.وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ.اورجومظلوم قتل کیا جاوے ہم نے اس کے ولی کوغلبہ یاحجت دی ہے.ولی کے معنی ولی ہروہ شخص ہے جوکسی کی وراثت کا حقدار ہو.اورایسے شخص کو بھی ولی کہتے ہیں کہ جس کو وہ خود مقررکردے.جیسے کہ مروی ہے کہ جب دشمن حضرت عثمانؓ کے خلاف منصوبے کررہے تھے.حضرت معاویہ ؓ نے ان سے درخواست کی کہ آ پ مجھے اپنا ولی بنادیں تاکہ ان لوگوں پر رعب ہواور وہ سمجھیں کہ عثمان کے قتل کابدلہ لینے والا ایک شخص موجود ہے.تواس کے جواب میں حضر ت عثمانؓ نے فرمایا کہ تمہارے متعلق احتمال ہے کہ تم مسلمانوں پرسختی کروگے میں تم کوولی نہیں مقررکرتا.اس سے یہ مستنبط ہوتاہے کہ ایساولی بناناجائز ہے.
Page 343
ًسلطان سے مراد سُلْطَان سے مراد غلبہ یا حجت ہے یعنی تم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس شکایت کرے اوراپنا حق لے لیو ے اورپھر حاکم کے فیصلہ کرچکنے کے بعد خواہ قاتل کوقتل کرے خواہ معاف کرے.لیکن اگر گورنمنٹ سمجھے کہ مقتول کاولی شرارت سے معافی دے رہا ہے توپھراسے بھی حق ہے کہ وہ قتل کی سزاجاری کردے.کیونکہ اپنے حقوق کو جائزطور پر ادانہ کرنے کی صورت میں یابوجہ خوف ادانہ کراسکنے کی صورت میں ولایت حکومت کی طر ف منتقل ہوجاتی ہے.قصاص میں ذاتی حق کے علاوہ قومی حق بھی ہوتا ہے تمام قصاص کے مسائل میں یہ حکم جاری ہے اوراس کی ایک عمدہ مثال حضرت علیؓ کے عمل سے ملتی ہے آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص نے دوسرے کو پِیٹاہے.حضرت علی ؓنے اس کوروکا اورمضروب کو کہا کہ اب تم اس کو مارو.مگرمضروب نے کہا کہ میں اس کومعاف کرتا ہوں.حضرت علیؓ نے سمجھ لیا کہ ڈر کے مارے اس نے اسے مارنے سے انکار کیا ہے کیونکہ وہ مارنے والا بڑاجبار شخص تھا.اس لئے آپ نے فرمایا تم نے اپنا ذاتی حق معاف کردیا ہے مگر میں اب قو می حق کو استعمال کرتاہوں.اور اُسے اسی قدر پِٹوادیا جس قدرکہ اس نے دوسرے کمزو رشخص کو پیٹاتھا.قاتل کے حقوق کی حفاظت یہ جوفرمایا کہ فَلَا يُسْرِفْ فِّي الْقَتْلِ اس میں قاتل کے حقوق کی حفاظت کی ہے.قصاص میں کئی قسم کی زیادتیاں ہوسکتی ہیں (۱) تکلیف سے قتل کیاجاوے مثلاً کسی کو جلاد مقرر کیا جائے اوروہ کُند آلہ سے قتل کرے (۲) موقعہ معافی کاہو مگروہ زوردے کہ نہیں میں ضرورہی قتل کروں گا.اسی طرح اور کئی طریقے اسراف کے ہوسکتے ہیں.مقتول کے ورثاء کو معاف کرنے کی تلقین لَایُسْرِفْ کے الفاظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ گوجان کے بدلہ میں جان کاعام قانون ہے.مگروارثانِ مقتول کوہمیشہ قتل کے بعد قتل پرعمل نہیں کرناچاہیے اورقتل کے فعل کو بڑھانانہیں چاہیے.یعنی جہاںتک ہوسکے قاتل کو اگرکسی طرح بھی اس کی اصلاح کی امید کی جاسکتی ہو.معاف کردینا چاہیے.اس حکم سے اسلام نے ملک کے امن کی بنیاد قائم کردی ہے.دنیا کاامن دوغلطیوں میں سے ایک کی وجہ سے بربادہوتاہے.یاتوجب قاتلوں کو ان کے کئے کی سزانہیں ملتی یاجب اندھادھند سزادی جاتی ہے.بعض دفعہ معاف کردینا ہی آئندہ امن پیداکرنے کاموجب ہوسکتا ہے.مگرموجودہ قانون وارثان مقتول کو ایساکوئی اختیار نہیں دیتا اورہرقتل کے بدلہ میں قتل ہی کرتا ہے.اس سے ملک کا امن برباد ہوتاہے اوردشمنیاںبڑھتی جاتی ہیں.اگراسلامی تعلیم پر عمل ہوتا توقتل بہت کم ہوجا تااوربُغض کم ہوجاتے.
Page 344
شرعاً کسی کو آپ ہی مجرم قرار دے دینا منع ہے یہ بھی یا درہے کہ شرعًا یہ بھی منع ہے کہ کوئی شخص آپ ہی کسی کو مجرم قرار دے کر اُسے سزادےدے.اگر کوئی ایساکرے تویہ بھی اسراف فی القتل سمجھا جائے گا.ایک حدیث میں آتاہے کہ قَالَ یَارَسُوْلَ اللہِ اِنْ وَجَدْتُ مَعَ اِمْرَ أَتِیْ رَجُلًا أُمْھِلُہُ حَتّٰی آتِیَ بِاَرْبَعَۃِ شُھَدَاءَ قَالَ نَعَمْ (مسند احمد بن حنبل مسند ابو ہریرۃؓ)ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یارسول اللہ اگر میں کسی شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھو ں تواسے قتل کروں یاانتظار کروں اورچارگواہ لاکر ثبوت بہم پہنچائوں.آپؐ نے فرمایا.چارگواہ لائو.ایک اورحدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم خود ہی قتل کروگے توقتل کے مرتکب سمجھے جائو گے.اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا.میں اسی طرف اشارہ کیا ہے.کیونکہ اس کے معنے ہیں کہ مقتول کے ولی کو حکومت کی طرف سے مدد دی جائے گی اس لئے خود ہی فیصلہ اورخود ہی اجراء نہ کرے بلکہ حکومت کے ذریعہ فیصلہ کرائے.اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًاکے الفاظ میں لَایُسْرِفْ فِّی الْقَتْلِ کی دلیل بھی بیان کی گئی ہے.یعنی وارث کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں امن قائم رکھنے کافرض اس کے ذمہ بھی ہے.پس چاہیے کہ وہ بھی ظلم نہ کرے اوریاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ا س کے حقوق کی حفاظت کی ہے.پس اسے بھی دوسروں کے حقوق کاخیال رکھنا چاہیے اورجس حکومت نے اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے ظلم کرکے اس کے نظام میں خلل نہیں ڈالناچاہیے.وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى اور تم اس طریق کے سواجو(یتیم کے حق میں )زیادہ اچھا ہو(کسی اورطورپر)یتیم کے مال کے پاس (تک بھی)نہ يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ١۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ١ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ پھٹکو یہاں تک کہ وہ اپنی مضبوطی کی عمر کوپہنچ جائے.اور(اپنے )عہد کو پوراکرو (کیونکہ)ہرعہد کی نسبت یقیناً مَسْـُٔوْلًا۰۰۳۵ (ایک نہ ایک دن )باز پُرس ہوگی.حلّ لُغَات.اَلْعَھْدُ اَلْعَھْدُکے لئے دیکھو رعدآیت نمبر۲۱.
Page 345
اَلْعَہْدُ.اَلوَصِیَّۃُ.وصیت اَلْیَمِیْنُ یَحْلِفُ بِھَا الرَّجُلُ.قسم.اَلْمَوْثِقُ.پختہ بات.اَلْمِیْثَاقُ.پختہ اقرار.الَّذِیْ یَکْتُبُہٗ وَلِیُّ الْاَمْرِ لِلْوُلَاۃِ اِیْذَانًا بِتَوْلِیَتِھِمْ.بادشاہ اپنے ماتحت افسران کو جو ان کی تقرری کا حکم نامہ لکھ کر دیتا ہے.(اقرب) تفسیر.بچے زیادہ طور پر اتفاقی حادثات کے نتیجہ میں یتیم ہوتے ہیں جن میں قتل،وبائیں وغیرہ شامل ہیں.پس قتل کے حکم کے بعد جس سے دوگھروں میں بچے یتیم رہ جائیں گے مقتول کے گھر میں بھی اورقاتل کے گھر میں بھی.جب وہ قتل کی سزامیں قتل کیاجائے گا.یتامیٰ کے حقوق کو بیان کیا.یتامیٰ کے مال کی حفاظت کا طریق اس بارہ میں فرماتا ہے کہ یتامیٰ کے مال کے قریب بھی نہ جائو.اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ یعنی صرف ایک طریق ایک کے مال پر تصرف کرنے کاہے کہ اس سے بہتر سے بہتر نتیجہ پیدا کیا جائے.یعنی صرف یہی نہیں کہ ان کے مال کو ناجائز طورپر استعمال نہ کرو بلکہ ان کو اس طرح استعمال کرو کہ وہ مال بڑھیں اوریتیموں کافائدہ ہو اس آیت میں اسلامی نظام کاایک اورایساحکم بیان کیاگیا ہے جس میں اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز اورمنفردہے یتیموں سے حسن سلوک کاحکم توسب مذاہب میں ملتاہے.لیکن یہ حکم کہ ان کے اموال کی حفاظت کرو اوران کو بڑھانے کی کوشش کرو.کسی اورمذہب میں نہیں ملتا.گویااس آیت میں ایک عام کورٹ آف وارڈز مقررکیاگیا ہے یعنی نابالغوں کی جائداد کی حفاظت کرنے والامحکمہ.آج کل مغربی حکومتوں کے ماتحت اس حکم پر عمل ہو رہاہے.مگر اس خیال کی بنیاد اسلام نے ہی آج سے تیرہ سوسال پہلے قائم کی ہے.یتیم کی حدجوانی سے مراد حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ سے یہ مراد نہیں کہ جب وہ جوان ہوجائیں.توان کے اموال کھانے جائز ہیں.کیونکہ اول تو یتیم جب بڑاہوجائے گا تووہ اپنامال کھانے ہی کیوں دے گا.دوسرے یہ خلاف عقل ہے کہ جب تک یتیم اپنے مال کو استعما ل نہ کرسکتاتھا.اس وقت تک تو اس کے مال کو بڑھایا جائے اورجب اس کے استعمال کرنے کا موقعہ آئے تواس کو کھاناشروع کردیاجائے.اسلام کسی کامال کھانے کی اجازت نہیں دیتا خواہ وہ یتیم ہو یاغیر یتیم.پس اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ جب تک وہ عقل کی اس حد کو نہ پہنچ جائے کہ وہ خود اپنے مال کو سنبھال سکے اس وقت تک حفاظت کرنی چاہیے اوردرمیان میں ہی اس کی حفاظت نہ چھوڑ دینی چاہیے.مثلاً جب دس بارہ سال کاہوگیا توکہہ دیاکہ اب بڑاہوگیا ہے خود مال سنبھال لے گا.غرض جوانی تک پہنچنے کی قید ا س لئے نہیں کہ اس کے بعد بے شک اس کا مال کھائو.بلکہ یہ قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ پوری جوانی سے پہلے جبکہ وہ مال کی حفاظت کے قابل ہوجائے.رشتہ داروں یاحکومت کو اس کی امداد چھوڑ نہ دینی چاہیے.دوسرے ان الفاظ سے اس
Page 346
طرف اشارہ کیا گیاہے کہ جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جاوے اوراپنی اس عقل کو پہونچ جاوے کہ جس میں وہ اپنے مال کی حفاظت کرسکتا ہوتواس وقت اس کے مال کو یہ کہہ کر کہ ابھی چھوٹاہے دبانہیں چھوڑناچاہیے.غرض حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ نے دونوں صورتوں سے جویتیم کونقصان پہنچانے والی ہیں اس کے رشتہ داروں اورحکومت کوروک دیا ہے ایسے بہت سے نظارے دنیا میں ملتے ہیں کہ رشتہ دار ایک مدت تک یتامیٰ کاکام کرنے کے بعد تھک کر کام چھوڑ بیٹھتے ہیں اوریتامیٰ کانقصان ہو جاتا ہے یاوہ جوان ہوجاتے ہیں لیکن ان کا حق ان کونہیں دیاجاتا.ریاستوں میں ایسے نظارے بہت دیکھنے میں آتے ہیں کہ رئیس جوان ہو جاتا ہے مگر جوافسر ریاست کے انتظام کے لئے مقر ر ہوتے ہیں اپنے ذاتی اغراض کو پوراکرنے کے لئے انہیں نابالغ یا غیر عاقل ہی قرار دیتے جاتے ہیں.اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ کا یتامیٰ کے ذکر سے تعلق وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ.اپنے عہد کوپوراکر و.بظاہر تویہ فقر ہ یتامیٰ کے ذکر میں بے جوڑ معلوم ہو تاہے.کیونکہ یتیم کاعہد سے کوئی خاص تعلق نظرنہیں آتا.لیکن حقیقت میں ایسانہیں کیونکہ(۱)عہد کے معنے ذمہ واری کے بھی ہوتے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں.فُلَانٌ وَلِیَ الْعَھْدَ.یعنی حکومت کی ذمہ واری کاولی ہے ان معنوں کے روسے اس جملہ کے معنی ہوں گے.کہ یتامیٰ کے متعلق اپنی ذمہ واری کو پورا کرو.جب تک ان کے مال کے انتظام کی ضرورت ہے انتظام کرو.اورجب ان کامال ان کے سپرد کرنے کا وقت آئے توان کامال انہیں دےدو.دوسرے اس طرف بھی اشارہ کیا گیاہے کہ یتامیٰ کے اموال کی حفاظت کوئی احسان نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کاحکم اوراسلامی نظام کاایک حصہ ہے.اس لئے احسان سمجھ کراس کام کونہ کروبلکہ فرض سمجھ کر کرو.(۲)چونکہ یتیم اپنے مال کی کمی بیشی کے متعلق کچھ دریافت نہیں کرسکتا اس لئے خدا تعالیٰ نے یتیم کے مال کو اپنے عہد میں شامل کرلیاہے تاکہ کوئی یہ سمجھ کر مال کو کھا نہ جاوے کہ اگر ہم کھاجائیں گے توکون پوچھے گا.اس لئے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا توہم پوچھیں گے یہ ہماراعہد ہے.(۳)یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یتیم کا ذکر کرکے ان لوگوں کا ذکر بھی ساتھ کردیاجویتامیٰ تونہیں ہوتے مگریتامیٰ سے مشابہ ہوتے ہیں.مثلاً کمزوراقوا م جو اپنے آپ کو طاقتور اقوام کی حفاظت میں دےدیتی ہیں.پس یتامیٰ کے ذکر کے ساتھ ان کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی کہ بعض اقوام بمنزلہ یتامیٰ ہوتی ہیں اوران کے حقوق تمہارے قبضہ میں آجاتے ہیں.بیشک تمہارا فرض ہے کہ اس وقت تم ان کے حقوق کی نگہداشت کرو لیکن ہمیشہ کے لئے ان پرتصرف قائم نہ رکھو بلکہ جب ان میں اہلیت پیداہوجائے انہیں ان کے مال سپردکردو.اگردنیا اس حکم پرعمل کرے تویہ قومی تنافر جو آج پیدا ہو رہا ہے یکدم دور ہوجائے.اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض وقت ایک زبردست قوم
Page 347
کمزورقوم کے حقوق کی حفاظت کے لئے اس کی نگرانی کاکام اپنے ہاتھ میں لینے پرمجبورہوجاتی ہے مگراس کافرض ہوناچاہیے کہ اس ماتحت قوم کے اند رصلاحیت پیداہوجانے پر جلد سے جلد اسے اپنے اموال میں تصرف دےدے اوراس کی بلوغتِ قو می کے بعد اس کے ملک اورمال پر قبضہ نہ رکھے.وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ١ؕ اورجب تم (کسی کوکچھ)ماپ کر دینے لگو تو ماپ پورادیاکرو اور(جب تول کر دوتو)سیدھے ترازو کے ساتھ تول کر د و ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا۰۰۳۶ یہ بات سب سے بہتر اورانجام کے لحاظ سے سب سے اچھی ہے.حلّ لُغَات.اَلْکَیْلُ کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۶۰.اَلْکَیْلُ: کَالَ الطَّعَامَ کَیْلًا وَاِکْتَالَہُ بمعنًی کَیْلُ کَالَ میں سے ہے اور کَالَ اور اِکْتَالَ دونوں کے معنے ہیں.ماپا.ثعلب امام لغت و دیگر محققین کا اختلاف چنانچہ ثعلب امام لغت کا یہی قول ہے وَقَالَ غَیْرُہُ اِکْتَلْتُ عَلَیْہِ: اَخَذْتُ مِنْہُ اور باقی محققین لغت کہتے ہیں کہ یہ معنی علیٰ کی وجہ سے نہیں.اِکْتَالَ کے معنی ہی یہی ہیں اور اس کا صلہ علٰی ہوتا ہے.یُقَالُ کَالَ الْمُعْطِیْ وَاکْتَالَ الَاٰخِذُ.کَالَ کا لفظ ماپ کر دینے کے لئے مخصوص ہے.اور اِکْتَالَ کا لفظ لینے کے لئے.کَالَہُ طَعَامًا وَکَالَ لَہُ بِمَعْنًی اور کَالَ بغیر صلہ کے بھی متعدی ہوتا ہے اور صلہ لام کے ساتھ بھی.اور دونوں صورتوں میں معنے ایک ہی ہوتے ہیں.یعنی ماپ کر دیا.وَالْکَیْلُ وَالْمِکْیَلُ: مَاکِیْلَ بِہٖ حَدِیْدًا کَانَ اَوْخَشَبًا اور کَیْلُ کے ایک معنے لفظ مِکْیلٌ کی طرح ماپنے کے آلہ کے بھی ہیں خواہ لوہے کا ہو یا لکڑی کا.وَکالَ الدَّرَاھِمَ وَ زَنَھَا سکوں کے ساتھ یہ لفظ آئے تو اس کے معنے وزن کرنے کے ہوتے ہیں.کُلُّ مَا وُزِنَ فَقَدْ کِیْلَ وزن کرنے کا دوسرا نام کیل بھی ہے.اس لئے ہر تولنے کی چیز کے لئے وزن کی بجائے کیل کا لفظ استعمال ہوسکتا ہے.(تاج) قِسْطَاسقِسْطَاسٌکے معنے ہیں.اَلْمِیْزَانُ.ترازو.وَاَقْوَمُ الْمَوَازِیْنَ وَقِیْلَ ھُوَ مِیْزَانُ العَدْلِ سیدھا اوردرست ترازو(اقرب)
Page 348
تفسیر.چونکہ پچھلی آیت میں حقوق کی واپسی کاحکم دیاتھا.اس لئے اس کے ساتھ ملتاہواحکم اس کے بعد بیان کردیا اورفرمایا کہ جس طرح یتیم کواس کامال اداکرنے کاحکم ہے اسی طرح آپس کے کاروبار میں ایک دوسرے کاحق پورا ادا کرنے کابھی ہم حکم دیتے ہیں.ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا کہہ کر اس طرف اشار ہ کیا ہے کہ یہ عمل دینی لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے اوردُنیوی انجام کے لحاظ سے بھی.کیونکہ جس تاجر کے متعلق لوگوں کوعلم ہوجائے کہ وہ کم تولتا ہے یاجس قوم کے متعلق یہ یقین ہوجائے کہ اس کالین دین اچھا نہیں اس کی تجارت کو آخر نقصان پہنچ جاتا ہے.وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ١ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ اور(اے مخاطب)جس بات کاتجھے علم نہ ہواس کی اتباع نہ کیا کر (کیونکہ )کان اورآنکھ اوردل الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا۰۰۳۷ ان سب کے متعلق پوچھا جائے گا.حلّ لُغَات.لَاتَقْفُ.لَاتَقْفُ قَفَاسے نہی مخاطب کاصیغہ ہے.اورقَفَا أَثَرَہٗ (یَقْفُوْ) کے معنے ہیں.تَبِعَہٗ.اس کی پیر وی کی.قَفَا فُلَا نًا بِاَمْرٍ:اٰثَرَہٗ بِہٖ.کسی چیز کے متعلق اسے ترجیح دی (اقرب)پس لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌکے معنے ہو ں گے اے مخاطب تواس کی پیروی نہ کر جس کاتجھے علم نہیں.تفسیر.بدظنی کی تشریح اس سے یہ مطلب نہیںکہ کوئی نیاعلم نہ سیکھو اورنئی نئی تحقیقاتیں نہ کرو.بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدظنی نہ کرو اور بغیر تحقیق کے دوسروں پر الزام نہ لگائو.چنانچہ اس کے آگے وہ اسباب جن سے بدظنی پیداہوتی ہے بیان کئے ہیں.یعنی کان آنکھ اوردل.بعض دفعہ انسان دوسرے کے متعلق بات سن کر اس بات کوپلے باندھ لیتا ہے اوربغیر تحقیق دشمنی شروع کردیتاہے.بعض دفعہ ایک واقعہ دیکھتا ہے اوراس سے غلط نتیجہ نکال لیتا ہے اوریہ تحقیق نہیں کرتاکہ ممکن ہے کہ اس فعل کی کوئی جائزوجہ ہو جسے دیکھ کراس نے بُراسمجھ لیا.اوربعض آپ ہی آپ اپنے دل میں ایک بات پیداکرلیتے ہیں.ان سب باتوں سے روکااورفرمایا کہ ظنی باتوں کے پیچھے نہیں پڑناچاہیے.بدظنی کے موجبات بدظنی کے موجبات میں کان سب سے بڑاموجب ہے.زیادہ ترلوگوں سے باتیں سن کر
Page 349
لوگ بدظنی کرتے ہیں.اس لئے اس کا ذکر پہلے کیا.اس کے بعد دوسرابڑاذریعہ آنکھ ہے اسے دوسرے نمبر پر بیان کیا.اس کے بعد انتہاء کی بدظنی کرنے والا شخص وہ ہوتاہے کہ نہ شکایت سنتا ہے نہ کوئی بات مشتبہ دیکھتا ہے بلکہ آپ ہی آپ دل میں ایک وجہ بناکر دوسروں کے پیچھے پڑ جاتاہے.اس کو سب سے آخر میں رکھا کہ یہ موجب سب سے کم ہے.کیونکہ خطرناک مریض عام مریضوں سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں.اِنَّ السَّمْعَ الخ.اس جملہ سے یہ بھی اشارہ کیاگیاہے کہ یہ مت خیال کرو کہ صرف مال و جان کے معاملہ میں ظلم میں گرفت ہوگی بلکہ انسانی عزت پر حملہ کے متعلق بھی پرسش کی جائے گی.اگر کوئی کان دوسرے کی نسبت وہ بات سنے گا جس کے سننے کااس کوحق نہ تھا تواس پر بھی پرسش ہوگی.اگرآنکھ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کرے گی جس کے دیکھنے کااس کوحق نہیں تواس کے بارہ میں بھی پرسش ہو گی.اگر کوئی دل ایسے خیالات رکھے گا جن کے رکھنے کااسے حق نہیں تواس کے متعلق بھی پرسش ہوگی.یہ ایسی اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی کی تعلیم ہے کہ اس پرعمل کرکے کسی قسم کاگند انسان میں باقی نہیں رہ سکتا.کسی فیصلہ کی بنیاد سوء ظن پر نہ ہو اس تعلیم میں اخلاق کے متعلق نہایت اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے انسان کو اپنے فیصلوں کی بنیاد ظن پر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ علم پر رکھنی چاہیے.محض کان کی شہادت یاآنکھ کی شہادت یادل کی شہادت کافی نہیں.بلکہ تمام ذرائع سے تحقیق کرکے پھر فیصلہ کرناچاہیے.حضرت امام ابوحنیفہ ؒ کاایک مشہور قو ل ہے کہ’’اگر کسی میں ننانوے وجوہ کفر کے ہوں اورایک وجہ ایمان کی تواس کوکافر مت کہو ‘‘.اس پُرحکمت ارشاد کایہی مطلب ہے کہ اگر ننانوے دلائل اس کے کفرکے ہوں اورایک دلیل ایمان کی ہوتوبھی اسے کافر نہ کہو.یہ مطلب ہرگز نہیں جیسا کہ بعض احمق خیال کرتے ہیں کہ ننانوے شرعی وجوہ کفرکے ہوں تب بھی اسے کافر نہ کہو.کفر کے اسباب تو ہیںہی سات آٹھ.اللہ کاانکار.ملائکہ کاانکار.کتب سماویہ کاانکار.انبیاء کاانکار.دعا کا انکار.قضاو قد رکاانکار اورحشر بعد الموت کاانکار.پس اگراس کے یہ معنے لئے جائیں کہ ننانوے اسباب کفرکے ہوںپھر بھی کافر نہ کہو توکسی دہریہ کوبھی کافر نہیں کہاجاسکتا.
Page 350
وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا١ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ اورزمین پر اکڑ کر مت چل.تونہ(تو)زمین کوپھاڑ سکتا ہے وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا۰۰۳۸ اورنہ پہاڑوں کی بلندی کوپاسکتا ہے.حلّ لُغَات.مَرَحًا.مَرِحَ الرَّجُلُ (یَمْرَحُ)مَرَحًا کے معنے ہیں.اِشْتَدَّ فَرْحُہُ وَنَشَاطُہُ حتّٰی جَاوَزَالقَدْرَوَتَبَخْتَرَ.حددرجہ کاخوش ہو کر متکبرانہ چال چلا.وَاخْتَالَ.اکڑ کرچلا (اقرب)پس لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًاکے معنے ہوں گے زمین پر اکڑ کرنہ چل.لَنْ تَخْرقَ.لَنْ تَخْرِقَ خَرَقَ سے مضارع واحد مخاطب کا صیغہ ہے.اورخَرَقَ الثَّوْبَ کے معنے ہیں.مَزَّقْتَہٗ فَتَمَزَّقَ.کپڑے کوپھاڑاتووہ پھٹ گیا.خَرَقَ الْمَفَازَۃَ:قَطَعَھَا حَتّٰی بَلَغَ اَقْصَاھَا.جنگل کو طے کیا اوراس کے آخر تک پہنچا (اقرب) پس لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ کے معنے ہوں گے.توزمین کے سفر کو طے کرکے ا س کے باہر نہیں نکل سکتا.تفسیر.پہلے اس وقت تک توان اخلاق کا ذکر فرمایا گیا تھا جن کاتعلق خدا تعالیٰ سے یا دوسرے انسانوں سے ہے.اب ان اخلاق کے متعلق ارشاد فرماتا ہے جو اس کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں.چنانچہ فرماتا ہے.کہ اگرتمہارے اندر کوئی خوبی کی بات ہو تواس کوتکبر کاذریعہ نہ بنائو کیونکہ اس طرح تم نیکیوں سے محروم ہوجائو گے اورآئندہ ترقی کی طرف قدم نہ اٹھا سکو گے.کیونکہ جو متکبر ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھنے لگ جاتاہے کہ میں نے انتہائی عرو ج پالیا ہے اوراس طرح وہ مزید ترقی سے محروم ہو جاتا ہے.دوسرے اس میں اس طر ف بھی اشارہ ہے کہ اے انسان تیری کامیابی آخر انسانی کامیابی ہے اس لئے اتنی ہی خوشی کرجو انسانوں کے لئے مقدر ہے اوریہ یاد رکھ کہ تواپنے کمالات کے باوجود زمین کو نہیں پھا ڑسکتا یعنی اس کے باہر نہیں جاسکتا.عربی محاورہ ہے خَرَقَ الْمَفَازَۃَ.جنگل کو طے کرکے نکل گیا.یہی معنے اس جگہ لگتے ہیں اورمراد یہ ہے کہ آخر تونے اسی دنیا میں رہنا ہے تیری ترقیاں محدود ہیں پس اپنے آپ کوایسانہ بنا کہ دوسرے انسانوں سے تیراگذارہ مشکل ہوجائے.
Page 351
متکبر انسان کا مرقع زندگی جن لوگوں کو متکبر لوگوں کے دیکھنے کاموقع ملاہے.و ہ جانتے ہیں کہ متکبر آدمی کی زندگی سخت تلخ گذرتی ہے.کیونکہ ایک طرف تو وہ اپنے آپ کو کوئی عجیب چیز سمجھنے لگتاہے دوسری طرف اسے اپنے ابناء وطن کے ساتھ مل کررہنا پڑتا ہے.پس عجیب متضاد جذبات میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے.آجکل کاانگریزی خوان طبقہ جواپنے آپ کودوسرے ہندوستانیوں سے اعلیٰ سمجھتا ہے اوریو رپین ان کو منہ نہیں لگاتے اسی عذاب میں مبتلا ہے.جواس کے ہیں وہ ان میں رہنا پسند نہیں کرتا اورجن میں وہ رہناچاہتا ہے وہ اسے حقیر سمجھتے ہیں.پس فرمایاکہ آخر اپنے لوگوں میں تونے رہنا ہے پس دل کی ایسی کیفیت نہ بنا کہ تیری زندگی تجھ پروبال ہوجائے.جبال سے مراد قوم کے سردار اور عالم لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا.جبل کے معنے پہاڑبھی ہوتے ہیںاور سید القوم اورعالم قوم کے بھی (اقرب).یعنی قوم کاسردار اورقوم کاعالم.اس جگہ جبال سے مراد دوسرے معنے ہیں یعنی سرداران قو م اورعلماء قوم.اوریہ جو فرمایا کہ توسرداران قوم اورعلماء قوم کے برابر نہیں ہوسکتا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ قوم میں بڑائی خدمت سے ملتی ہے یاعلم سے اوریہ دونوں قسم کے لوگ انکسا ر کانمونہ ہوتے ہیں.جیسے کہ عر ب کامحاورہ ہے سَیِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُھُمْ یعنی قوم کاسردار درحقیقت قوم کاخاد م ہوتاہے.اسی طرح فرماتا ہے.اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا(الفاطر:۲۹)اللہ تعالیٰ سے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں یعنی جس قدر انسان علم میں ترقی کرتا جاتا ہے اس کی خشیت بڑھتی جاتی ہے.پس اس جملہ سے یہ بتایا ہے کہ تکبر کرکے تُوقوم کاسردار نہیں بن سکتا نہ قوم کے علماء میں شامل ہو سکتا ہے.کیونکہ تکبر توتجھ کو اپنی قوم سے دور کردیتاہے اوراسی طرح خدا سے بھی دور کردیتاہے پس اگر توبڑائی کاہی طالب ہے توبھی توتکبر سے اپنانقصا ن کرتاہے کیونکہ ا س فعل سے تُواپنے آپ کو اسی چیز سے محروم کرتاہے جس چیز کی تیرے دل میں خواہش ہے.پس تکبر نہ کر اگرتیرے اندر کوئی دنیوی خوبی ہے تواس کی مدد سے قوم کو فائدہ پہنچا.تاکہ توقوم کاسردار بن جائے اوراگر کوئی دینی خوبی ہے تواس کے ذریعہ سے قوم کو فائدہ پہنچا.تاکہ تو خدا تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہوجائے.کس لطیف پیرایہ میں یہاں تکبر سے روکاگیاہے.اس کی نظیر بھی دنیا کی کوئی کتاب پیش نہیں کرسکتی.كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا۰۰۳۹ ان میں سے ہرایک (فعل)کی بُری صور ت تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے.حلّ لُغَات.السَّیّءُ السَّیِّءُکے معنے ہیں اَلْقَبِیْحُ.بُری صورت (اقرب)
Page 352
تفسیر.ہر حکم کی تعمیل میں اعتدال کو ملحوظ رکھنے کی تلقین اس چھوٹے سے فقرہ میںگویادریا کو کوزہ میں بندکردیاگیا ہے.فرماتا ہے جس قدر احکام اوپربیان ہوئے ہیں ان کے بُرے پہلو بھی ہیں اوراچھے بھی.جوبرے پہلو ہیں ان کواللہ تعالیٰ ناپسند کرتاہے اچھوں کونہیں.یعنی کوئی فعل بھی دنیاکاایسانہیں جسے ہرحال میں بُراکہاجاسکے.توحید اچھی بات ہے لیکن اگرانسان توحید کوفساد کاموجب بنالے اوردوسری اقوام کے معبودوں پر آوازے کسے تویہی توحید بری ہوجائے گی ماں باپ کاادب اچھا فعل ہے لیکن ان کے کہنے پر شرک یا ظلم کرنے لگ جائے تویہ براہوجائے گا.قتل برافعل ہے لیکن دفاع قوم سے یا ضروری قصاص سے جی چرائے تویہ براہوگا.یتیموںکے مال کو ہاتھ نہ لگانااچھا ہے لیکن اگرگناہ کے ڈر سے ان کے مال کی حفاظت چھوڑ دے تویہ بھی براہوگا.دیانتداری کے غلط مفہوم سے بچنے کی تلقین سودے میں دیانت اچھی چیز ہے مگربددیانتی سے ڈر کر کسب حلال بھی چھو ڑ دے تو براہوگا.شہوانی قوتوںکو ان کے دائرہ میں رکھنا اچھا ہے لیکن ان کو بالکل نظر انداز کردینااوررہبانیت اختیار کرلینا یاان کو ناجائز طور پر استعمال کرنا برافعل ہوگا.بدظنی نہ کرنااچھا فعل ہے لیکن ایک پہرہ دار حسن ظنی سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو اپنی حفاظت کی اشیاء کے پاس جانے دے تویہ بُراہوگا.تکبر نہ کرنا اچھا فعل ہے لیکن بہادر ی اورجرأت دکھانے کے موقعہ پر انکسار دکھائے تویہ بھی براہوگا.پس فرمایا کہ احکام کی حکمتوںکو سمجھو اورموقع اور محل پر ہرقوت کو استعمال کرو.اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قوتوں کے استعمال سے نہیں روکتا بلکہ ان کے غلط استعمال سے روکتا ہے.انسانی اعمال کی یہ تشریح ایسی کامل ہے کہ اس کو نہ سمجھنے سے ہی سب خرابیاں پیداہوتی ہیں.مگرکتنے لوگ ہیں جواس میانہ روی پر کاربندہیں.ذٰلِكَ مِمَّاۤ اَوْحٰۤى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ١ؕ یہ (تعلیم)اس (علم اور)حکمت میں سے (ایک حصہ)ہے جوتیرے رب نے وحی کے ذریعہ سے تیری طرف بھیجی وَ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى ہے.اورتو اللہ(تعالیٰ)کے ساتھ کوئی اورمعبود مت بنا ورنہ توملامت کا نشانہ بن کر (اور) فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا۰۰۴۰ دھتکاراجاکر دوزخ میں ڈال دیاجائے گا.تفسیر.سبحان اللہ! کیاعجیب ترتیب ہے.پہلے سورۃ نحل میں فرمایاتھا کہ حکمت آنے والی ہے اب اس
Page 353
میں بتایاکہ ان حکمت کی باتوں میں سے چند ایک ہم نے اوپر بیان کی ہیں.اب لائوان کتابوں کو جو اس قرآن کریم سے پہلے تھیں اوردکھائوکہ ان میں ایسی تعلیم کہاں ہے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چندایک امور ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جن کو لے کر ہم اہل کتاب سے مباحثہ کرکے ان کو شکست دے سکتے ہیں.پہلے رکوع میں فرمایاتھا وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ.اس کے بعدتوحید کے عملی پہلو کو پہلے بیان کیا اور بتایاکہ اسلام کی توحید نے دنیا کو عملی طورپر کیا فائدہ پہنچایاہے.اب توحید کادوسراپہلو بیان کرتاہے اورفرماتا ہے کہ صرف دوسرے معبود کی عبادت سے انسان مشرک نہیں ہوتابلکہ اگر کوئی شخص اپنے ذہن میں بھی کسی کو خدا کاشریک خیال کرتاہو تووہ بھی مشرک ہے.تُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ.اس کاصرف یہی مطلب نہیں کہ آخرت کوجہنم میں ڈالاجائے گا بلکہ شرک کرنا خود ایک جہنم ہے کیونکہ جب کئی ایک کو معبود بنائے گا توکس کس کو خوش رکھے گااورکس کو ناراض کرے گا.موحد کے سامنے مشرک ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے دوسرے ا س طرح بھی یہ جہنم ہو جاتا ہے کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اورمشرک ہمیشہ موحدوں کے سامنے ذلیل ہوتاہے.آج عیسائیوں کو ہی دیکھ لو کہ ان کے لئے تثلیث کامسئلہ کس طرح ایک جہنم بن رہاہے.کسی سے پوچھ کردیکھ لو خواہ کتنا بڑاپادری ہو وہ اس کی کو ئی دلیل نہ دے سکے گا.صرف اورصرف توحید ہی ایک ایسامسئلہ ہے کہ جس کومان کرانسان آرام میں آجاتاہے اوراسی سے ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے.مَلُوْمًا.میں بتایاکہ مشرک کے سرپر ہمیشہ ملامت ہی رہتی ہے.ایک معبود کوماناتودوسرے کی ملامت سرپر آگئی.اُس کوماناتوتیسرے کی ملامت کا ہار گلے میں.پھر مَدْحُوْرًا کہہ کر بتا یا کہ ادھر تو ہر وقت کے دکھ میں مبتلا ہوتا ہے.ادھر آرام و راحت کے سر چشمہ یعنی خدا تعالیٰ سے بھی دور پھینکا جاتا ہے گویا نہ خدا ہی ملا نہ وصالِ صنم کی سی حالت اس کی ہو جاتی ہے.
Page 354
اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ اِنَاثًا١ؕ کیاتمہارے رب نے تم کولڑکوں(کی نعمت )سے مخصوص کردیا.اور(خود) اس نے بعض فرشتوں کو (اپنی )لڑکیاں اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًاؒ۰۰۴۱ بنایاہے.تم یقیناً (یہ )بڑی (خطرناک)بات کہتے ہو.حلّ لُغَات.اَفَأَصْفٰکُمْ أَصْفَی فُلَانًا بِکَذَا کے معنے ہیں اٰثَرَہٗ بِہٖ وَاخْتَصَّہٗ.کسی چیز کے متعلق اسے ترجیح دی.اوراس کواس کے لئے خاص کیا (اقرب) پس اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ کے معنے ہوں گے کہ کیاتم کو خدا تعالیٰ نے بیٹوں کے ساتھ مخصوص کیا.تفسیر.اس آیت میں اس ذہنی کش مکش اورشرمندگی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے فرماتا ہے کہ مشرکوں کے عقیدوں کو دیکھو کیسے عجیب ہیں.مثلاً یہ کہ بعض خدا تعالیٰ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اوراپنے لئے لڑکے.پھر ان ہی لڑکیوں کی پوجاکرتے ہیں جن کو وہ ذلیل قرار دیتے ہیں.گویاخدا تعالیٰ کو چھوڑ کر انہیں وجودوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے.جن کو ان کے دل ذلیل سمجھتے ہیں.قَوْلًا عَظِيْمًا سے مراد بیوقوفی کی بات ہے.عظیم بری چیز کے لئے آئے تواس کے معنے برائی میں زیادتی کے ہوتے ہیں اور اچھے معنوں میں آئے تو اچھی بات میں بڑائی مراد ہوتی ہے.اس جگہ اس لفظ سے یہ بتایاہے کہ مشرک کی عقل بھی ماری جاتی ہے وہ ایسی باتیں کرتاہے جوکوئی سمجھدار آدمی نہیں کرسکتا.مشرک کی ذہنیت کو ظاہر کر نے والا مہاراجہ کا واقعہ ا س موقعہ پر ایک لطیف واقعہ مجھے یاد آگیا وہ مشرک کی ذہنیت کوخوب منکشف کرتاہے.جموں کے ایک سابق مہاراجہ صاحب کے پاس استاذی المکر م حضرت مولوی نورالدین صاحب (اللہ تعالیٰ ان کے مدارج بلندکرے قرآن انہوں نے ہی مجھے پڑھایاتھا اللہ تعالیٰ نے اب مجھے بہت علم بخشا ہے بلکہ وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے تم سے ایسے ایسے معارف قرآن کے سنے ہیں جو نہ مجھے معلوم تھے اورنہ پہلی کتب میں درج ہیں.لیکن اس کتاب کی چاٹ انہوں نے ہی مجھے لگائی اوراس کی تفصیل کے متعلق صحیح راستہ پر ڈالا اوروہ بنیاد ڈالی جس پر میں عمارت تعمیر کرسکا.اس لئے دل ہمیشہ ان کے لئے دعاگورہتاہے ) بطورطبیب ملازم تھے اورشاہی طبیب کے عہدہ پر فائز تھے بعد میں ان مہاراجہ صاحب کے فوت ہونے پر ان کے
Page 355
بیٹے مہاراجہ پرتاب سنگھ صاحب نے ان کو جموں سے اس الزام پر نکال دیا کہ موجودہ مہاراجہ صاحب کے والد اورچچا راجہ امر سنگھ صاحب او رراجہ رام سنگھ صاحب سے ان کے گہرے تعلقات ہیں ایسا نہ ہوکہ ان کی خاطرمجھے زہر دےدیں.اس کے بعد وہ قادیان ہجرت کرکے آگئے اورآخر اپنے تقویٰ اورعلم کی وجہ سے جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ ہوئے.دوران ملازمت کاوہ قصہ سنایاکرتے تھے کہ ایک دن مہاراجہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولو ی صاحب آپ بھی کوئی بُت اپنے گھر رکھتے ہیں کہ نہیں.فرماتے تھے میں نے کہا مہاراجہ صاحب نہیں ہم بُت نہیں رکھتے ہمارے مذہب میں یہ منع ہے.اس پر کچھ حیران سے ہو کر کہنے لگے کہ ایک نصیحت آپ کوکرتاہوں کہ کالی دیوی کابُت ضروررکھ لیں.یہ بڑی سخت دیوی ہے اوربڑانقصان پہنچادیتی ہے.فرماتے تھے میں نے کہا.مہاراجہ صاحب ہم توکالی کوبھی نہیں رکھ سکتے.اس پر وہ کہنے لگے کہ پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا.میں نے کہا نہیں مہاراج کوئی نقصان نہیں ہوتا.یہ سن کر وہ کچھ تردّد میں پڑ گئے.تھوڑی دیر غورکرنے کے بعد بولے مولوی صاحب میں سمجھ گیا آپ کو میں جموں کی ریاست میں سزادینی چاہوں تودے سکتاہوں.لیکن آپ سیالکوٹ چلے جائیں توپھر کچھ نہیں کرسکتا.یہی معاملہ یہاں ہے.ہم توکالی دیوی کومان کراس کے اختیارمیں آگئے ہیں وہ ہمیں سزادے لیتی ہے.لیکن آپ لوگ سرے سے انکار کرکے اس کی حکومت سے نکل گئے ہیں اس لئے وہ آ پ کاکچھ بگاڑ نہیںسکتی.فرماتے تھے میں نے اس پر کہا مہاراج آپ خوب سمجھے ہم ایک خداوندکومان کر ان بتوں کے قبضے سے نکل چکے ہیں.اس پر مہاراجہ صاحب تو اپنی جگہ خوش کہ میں نے صحیح بات دریافت کرلی اورمیں اپنی جگہ خوش کہ توحید نے ہم کوکیسی کیسی لغویات سے بچالیا ہے.وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا١ؕ وَ مَا يَزِيْدُهُمْ اورہم نے اس قرآن میں (ہرایک بات کو )اس لئے بار بار بیان کیا ہے.کہ وہ (اس سے )نصیحت حاصل کریں اِلَّا نُفُوْرًا۰۰۴۲ اور(باوجود اس کے )وہ انہیں (عُجب و )نفرت ہی میں بڑھارہاہے.حلّ لُغَات.صَـرَّفْنَا.صَـرَّفْنَا صَـرَّفَ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے جوصَرَفَ سے مزید ثلاثی ہے اور صَـرَفَہٗ (صَـرْفًا)کے معنے ہیں رَدَّہٗ عَنْ وَجْھِہٖ اس کے ارادہ سے اسے پھیرا اور صَرَّفَ الْکَلَامَ کے معنے ہیں
Page 356
اِشْتَقَّ بَعْضَہٗ مِنْ بَعضٍ کلام کے ایک حصہ کودوسرے سے مشتق کیا.صَرَّفَ اللہُ الرِّیَاحَ:حَوَّلَھَا مِنْ وَجْہٍ الٰی وِجْہٍ.اللہ تعالیٰ نے ہوائوں کارخ ادہر سے ادہر پھرایا.صَرَّفَ فُلَانًا فِی الْاَمْرِ :قَلَّبَہٗ فِیْہِ وَفَوَّضَہٗ اِلَیْہِ کسی کام میں کسی کو لگایا اوروہ کام اس کے سپر دکیا (اقرب)پس وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِکے معنے ہوں گے.ہم نے قرآن مجید میں ہربات کو با ر بار بیان کیا ہے.نُفُوْرًا: نُفُوْرٌ نَفَرَ کامصدر ہے.اورنَفَرَتْ (تَنْفِرُ )اَلدَّابَۃُ کَذَا کے معنے ہیں جَزِعَتْ وَ تَبَاعَدَتْ.جانورڈرکردور بھاگا نَفَرَ الْقَوْمُ نَفْرًا:تَفَرَّقُوْا.لوگ پراگندہ ہوگئے نَفَرَالْقَوْمُ عَنْ کَذَا :اَعْرَضُوْا وَصَدُّوْا لوگوں نے کسی بات سے اعراض کیا اوراس سے رُکے.نَفَرَ القَوْمُ مِنْ کَذَا.أَنِفُوْا وَ کَرِھُوْہُ لوگوں نے اس سے ناک چڑھایا اوراس کو ناپسند کیا.(اقرب)پس نُفُوْرٌکے معنے ہوں گے.دورہونا.پراگندہ ہونا.اعراض کرنا.ناپسند کرنا.تفسیر.نُفُوْرًا کے معنے اوپر بتائے جاچکے ہیں.کہ دور ہونے.پر اگندہ ہونے.ناپسند کرکے.اعراض کرنے کے ہوتے ہیں.ان معنوں کے لحاظ سےوَ مَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا.کے یہ معنے ہوئے کہ نہیں زیادہ کرتا ان کو مگر دور ہونے میں.پراگندہ ہونے میں.ناپسند کرنے میں یااعراض کرنے میں.یعنی ہم نے قرآن کریم میں قسم قسم کے دلائل بیان کئے ہیںمگرلوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے نفرت ہی کرتے ہیں.اس سے اعراض ہی کرتے ہیں.قرآن کریم میں واقعات کے تکرار سے آنے کی وجہ بعض لوگ اعترا ض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں تکرارہے(تفسیر القرآن از ویری جلد سوم صفحہ ۶۲).مگر دیکھو قرآن کریم نے خود ہی اس کا جواب دےدیاہے فرماتا ہے.وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ ہم نے اس قرآن میں ہرپہلو سے مسائل کی بحث کی ہے تاکہ کسی پہلو سے ہی لوگ سمجھیں تب بھی لوگ اعراض کررہے ہیں.صَـرَّفَ کے معنے کسی چیز کو اچھی طرح سے ردّکرنے کے بھی ہوتے ہیں اورادھر سے ادھر پھرانے کے بھی.چنانچہ عر بی کامحاورہ ہے صَرَّفَ اللہُ الرِّیَاحَ جس کے معنے ہیں حَوَّلَھَا مِنْ وَجْہٍ اِلَی وَجْہٍ یعنی ہوائوں کارخ ادھر سے ادھر پھیرادیا.ان دونوں معنوں کو ملحوظ رکھ کر آیت کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ (۱)اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح تمام اعتراضات کودورکرتاہے (۲)اللہ تعالیٰ ہر مضمون کو مختلف پہلوئوں سے بیان کرتاہے.یہ دونوں باتیں قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں.تمام اعتراضا ت جو قرآ ن پر وارد ہوتے ہیں ان کو اس میں خو ب اچھی طرح ردّ کیا گیا ہے اور تمام ضروری امورکو مختلف پہلوئوں سے کھو لا گیا ہے.پس جس کلام نے ہر مسئلہ
Page 357
پر بالا ستیعاب بحث کرنی ہو لازماً اس میں وہ امور متعددبار بیان ہوں گے.اور اسے کوئی عقلمند تکرار نہیں کہہ سکتا.تکرار تو یہ ہے کہ بے وجہ ایک بات کو دہرایا جاوے.مگر جب ہر دفعہ دوسرے پہلو سے یا دوسری ضرورت سے بات بیان کی جائے تو یہ تکرار کس طرح کہلا سکتی ہے.اصل بات یہ ہے کہ لوگ غور کر کے قرآن کے مضمونوں کو سمجھتے نہیں اور یونہی سطحی باتوںکی وجہ سے اعتراض کردیتے ہیں.وَمَایَزِیْدُھُمْ اِلَّانُفُوْرًا نے واضح کیا کہ ہمارے باربار سمجھا نے اورپھر بھی ان کے نہ ماننے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شرک کی وجہ سے ان کی عقل ماری گئی ہے.ورنہ کیاوجہ ہے کہ ہمارے طرح طرح پر سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھتے.قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى توکہہ (کہ) اگر ان کے قول کے مطابق اس کے ساتھ (کوئی)اورمعبود(بھی )ہوتے تواس صورت میں وہ (یعنی ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا۰۰۴۳ مشرکین ان معبودوں کی مدد سے )عرش والے (خدا)تک (پہنچنے کا )کوئی راستہ ضرورڈھونڈ لیتے حلّ لُغَات.ذی العرش.ذِی الْعَرْشِ عرش والا.اَلْعَرْشُ کے لئے دیکھویونس آیت نمبر ۵.عَرَشَ.عَرَشَ عَرْشًا: بَنٰی بِنَاءً مِنْ خَشَبٍ لکڑی کی عمارت بنائی.اَلْبَیْتَ: بَنَاہُ تعمیر کیا.اَلْکَرْمَ: رَفَعَ دَوَاِلَیْہُ عَلَی الْخَشَبِ.بیل کو قرینے سے لگائی ہوئی لکڑیوں پر چڑھایا.(اقرب) اَلْعَرْشُ سَرِیْرُ الْمَلِکِ اورنگ شاہی.اَلْعِزُّ.عزت و غلبہ.قِوَامُ الْاَمْرِ معاملات اور امور کی درستی کا ذریعہ اور مدار.رُکْنُ الشَّیْءِ سہارا.مِنَ الْبَیْتِ :سَقْفُہُ چھت.اَلْخَیْمَۃُ خیمہ.اَلْبَیْتُ الَّذِیْ یُسْتَظَلُّ بِہٖ سایہ کا کام دینے والا گھر شِبْہُ بَیْتٍ مِنْ جَرِیْدٍ یُجْعَلُ فَوْقَہُ الثُّمامُ جھونپڑی.(اقرب) تفسیر.اس تصریف کی مثال بھی معاً دےدی.شرک کے مضمون کو پھر بیان کیا ہے لیکن اس میں ایک نئی دلیل پیش کی ہے یونہی پہلی بات نہیں دہرادی فرماتا ہے اگر شرک صحیح ہوتا تو کیا مشر ک لوگ خدا رسیدہ نہ ہو جاتے.اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًاکے معنے یہی ہیں کہ اگر شرک درست ہوتا تو مشرک لوگ ذی العرش کے ساتھ کوئی تعلق بنا ہی لیتے کیونکہ اس کی بیٹیوں یا بیٹوں سے تعلق پیدا کرکے ان کے لئے قرب کی راہیں کھل جانی چاہیے تھیں.
Page 358
ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں خود مشرکوں کا دعویٰ بیا ن کیا ہے کہ وہ بھی اسی غرض یعنی ’’تقرب الی اللہ ‘‘کے لئے ان کی عبادت کرتے تھے.جیسے کہ سورۃ زمر میں فرمایا مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى(الزمر:۴) کہ ہم توان بتوں کی اس لئے عبادت کررہے ہیںکہ وہ ہمیں خدا کا قرب دلادیں.یہاں ان کے اپنے دعوے کو ان کے شرک کے رد میں پیش کیاگیا ہے کہ جب ان کی غرض یہی ہے کہ ذی العرش تک پہنچیں.اورذی العرش کے مقربین سے انہوںنے تعلق بھی پیداکرلیا ہے توپھر توچاہیے توتھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوجاتے مگر اس کے کوئی آثار توان میں پائے نہیں جاتے.قرب الٰہی کے آثار قرآن شریف سے قرب الٰہی کے مندرجہ ذیل آثار معلوم ہوتے ہیں :.اول.دعا کاقبول ہونا.سورۃ بقرہ ع ۲۳ میں فرمایا ہے کہ وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ١ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ الآیہ(البقرة:۱۸۷).کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں توکہہ دے کہ میں تم سے قریب ہوں.اور میرے قریب ہونے کی یہ علامت ہے کہ پکارنے والے کی پکا ر کا جواب دیتاہوں.یہ ایسی علامت ہے کہ مشرک بھی اس کی صحت کاانکا ر نہیں کرسکتے.مگر یہ علامت کسی مشرک میں نہیں پائی جاتی.مشرکوں میں سے کوئی بھی ایسانہیں جسے قبولیت دعا کا دعویٰ ہو.آج تک ایک شخص بھی دنیا میں ایسانہیں پیداہواجس نے دعویٰ کیا ہو کہ مجھے ان بتوں کے ذریعہ سے خدامل گیا ہے.اوروہ میری دعائیں سنتا اورقبول فرماتا ہے اوردنیا نے اس کی قبولیت دعا کے نشان دیکھے ہوں.قرب الٰہی کا دوسرا معیار لغو اور گناہ سے بچناہے دوسرامعیار قرب الٰہی کا سورۃ واقعہ میں بیان ہواہے.وہاں مقربوں کا ذکرکر کے فرماتا ہے.لَایَسْمَعُوْنَ فِیْہَالَغْوًا وَلَاتَاثِیْمًـا اِلَّا قِیْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا (الواقعہ:۲۶،۲۷)یعنی قرب کا مقام وہ ہے جس میں لغواورگناہ کی بات کوئی نہیں ہوتی.اورلوگ ایک دوسرے کے شرسے بھی محفوظ رہتے ہیں.اورہرایک شخص دوسرے کی سلامتی تلاش کرتا ہے اوراللہ تعالیٰ سے بھی اسے سلامتی ملتی ہے.یہ معیار بھی ایسا نہیں کہ کو ئی مشرک اس کاانکا رکرسکے.ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا لغو باتوں سے اورگناہ سے بچے گا.اورخدا کابندہ ہوکر ا س کے دوسرے بندوں کی بھلائی میں لگارہے گافساد نہیں کرے گا.یہ علامتیں بھی کسی مشرک میں نہیں پائی جاسکتیں.پہلی بات لغو باتوں سے محفوظ ہوناہے.مشرک میں یہ بات کہاں پائی جاسکتی ہے.و ہ توشرک کی وجہ سے مضحکہ خیز باتیں کرتاہے.ایک بے خبر اوربے شر چیز کے سامنے سجدے کرتاہے اس کی عظمت کرتاہے.حتٰی کہ عقلمند اس کی حرکات کو دیکھ کر حیران رہ جاتاہے.بھلا یہ غوغا جو گائے کے تقدس
Page 359
کاہندوستا ن میں برپا ہے کونسامعقول شخص اسے جائز قرار دے سکتا ہے.گائے کے پرستار ا س کادود ھ اس کے بچہ سے چھڑالیتے ہیں.آپ غلہ کھاتے ہیں اسے گھاس کھلاتے ہیں.اسے باندھ کررکھتے ہیں.نر پر بوجھ لادتے ہیں.سواری کاکام لیتے ہیں.مارتے پیٹتے ہیں اورپھر وہ ماتاکی ماتاہے.پھر لطیفہ یہ کہ ہند و عیسائیوں پر تمسخر اڑاتے ہیں کہ وہ ایک کمزور بندہ کوخدابنارہے ہیں اوروہ ان پر ہنستے رہتےہیں کہ ایک کمزور جانور کو دیوی سمجھ رہے ہیں.ان لغو باتوں کو دیکھ کر ایک موحد بے ساختہ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللہِ کہہ اٹھتا ہے.دوسری علامت گنا ہ سے بچناہے.مشرک شرک کرتے ہوئے گنا ہ سے بچ ہی نہیں سکتا.بے شک مشرکوں میں سے بھی بعض نیک ہیں.لیکن ان کی نیکی شرک کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کے باوجود ہے.ایسے لوگوں کی فطرت اچھی ہوتی ہے.پس شرک ان کے اندر جڑ نہیں پکڑتا.مثلاً گائے ہی کولے لو جولوگ گائے کو پوجتے ہیں اس کو طرح طرح سے دکھ بھی دیتے ہیں.اوراس پر مجبور ہیں.کیونکہ گائے خدا تعالیٰ نے انسان کے کام کے لئے بنائی ہے.انہیں اس سے کام لینے کے بغیر کوئی چار ہ نہیں.اس کانتیجہ یہ ہوتاہے کہ و ہ گائے سے کام بھی لیتے جاتے ہیں اورساتھ ہی دل میں احساس گناہ بھی بڑھتاجاتاہے اورضمیر ناپاک ہوجاتی ہے.پھر دیکھو مشرک ہندو دسہر ہ مناتے ہیں.مگر پھر اس خیا ل سے کہ راون برہمن تھا اوررام کھتری.دسہر ہ منا کر ایک دن توبہ کارکھتے ہیں تابرہمن کی ہتک کاازالہ ہو جائے.عیسائیوں کابھی یہی حا ل ہے مسیح کو ایک طرف خدابناتے ہیں دوسری طرف اپنے گناہ اس پر لادتے ہیں.اور شرک کاعقید ہ ان کے لئے ہربدی کارستہ کھولتاہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے ہمارے گنا ہ اٹھالئے ہیں.تیسری علامت قرب الٰہی کی بندہ کی حفاظت ہے تیسری علامت قرب کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طر ف سے مقرب کوحفاظت ملتی ہے.یہ علامت بھی مشرک کو حاصل نہیں ہوتی اورنہ ہوسکتی ہے.جوان چیزوں کے تابع ہو جاتا ہے جن کو خدا تعالیٰ نے اس کے تابع بنایاتھا اس کے لئے حفاظت کا کونسا ذریعہ باقی رہ جاتاہے.چوتھی علامت قرب الٰہی کی باہمی صلح صفائی ہے چوتھی علامت یہ ہے کہ خدا کاہوکر اس کے بندوں سے نیک سلوک کرے اورآپس میں صلح صفائی پیداہو.یہ علامت بھی مشرک میں پیدا نہیں ہوسکتی.کیونکہ توحید ہی دنیا میں امن قائم کرسکتی ہے.مختلف خدائوں کی موجودگی میں تفرقہ اورفساد ہی پیداہو سکتا ہے.قومی دیوتائوں ہی کی وجہ سے اقوام میں جنگیں ہوتی ہیں.ہندومسیح کونہیں مان سکتا.مسیحی گائے کی پوجانہیں کرسکتا.مگر یہ سب ایک خدا کی پوجاکرسکتے ہیں.اوردنیا کاامن اس ذریعہ سے محفوظ ہو سکتا ہے.اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا کے یہ بھی معنے ہیں کہ اگردوسرے معبود سچے ہوتے تویہ لوگ ان کے ساتھ
Page 360
تعلق پیداکرکے کوئی کامیابی کی راہ میرے خلاف ڈھونڈ لیتے اورمجھے نقصان پہنچانے اورتباہ کرنے کاراستہ نکال لیتے اورا ن کی معرفت میرے خلاف کوئی تدبیر ہی ذی العرش سے پوچھ لیتے جس سے انہیں کامیابی حاصل ہوجاتی.مطلب یہ کہ کمزوری کے باوجود میرادن بدن بڑھنا اوران کا ان بتوں کی پرستش کرنے اوران کی مدد حاصل کرنے کے باوجود گھٹنا اس امر کی علامت ہے کہ شرک کاعقیدہ صحیح نہیں اورنہ اس میں کوئی فائد ہ ہے.تردید شرک کی واضح دلیل بتوں کا امداد نہ کر نا ہے یہ دلیل بعض بڑے بڑے مشرکوں کے لئے ہدایت کاموجب ہوئی ہے.حدیث میں آتاہے کہ فتح مکہ کے موقعہ پر نبی کریم صلعم نے عورتوں کی بیعت لیتے وقت فرمایاکہ اس امر کااقرار کرو کہ ہم شرک نہیں کریں گی.اس موقعہ پر ہندہ ابوسفیان کی بیوی بھی موجود تھی.وہ بے اختیار بول اُٹھی کہ یارسول اللہ!کیا اب بھی ہم شرک کریں گی.اگر ان بتوں میں کچھ طاقت ہوتی اوراگر یہ ہماری مدد کرسکتے توآپ اکیلے ہو کر بھلا ہم پر غالب آسکتے تھے؟ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا۰۰۴۴ وہ اس بات سے جو وہ (یعنی مشرکین )کہتے ہیں پاک اور بہت ہی بالاہے حل لغات.تَعٰلٰی تَعٰلٰی: اِرْتَفَعَ.تعالیٰ کے معنے ہیں بلندہوا(اقرب)پس تَعٰلٰی عَمَّا یَقُوْلُوْنَ کے معنے ہوں گے وہ اس بات سے بلند و بالاہے جو وہ کہتے ہیں.عُلُوًّا:عُلُوًّاعَلَا کامصدر ہے اورعلاکے معنے کے لئے دیکھو سور ۃہذا آیت نمبر ۵.تفسیر.اس آیت میں تَعٰلٰی کی تاکید غیر باب سے یعنی عُلُوًّاسے کی گئی ہے.قرآن کریم میں اس کی اورمثالیں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً فرماتا ہے اَنْبَتَھَا نَبَاتًاحَسَنًا.مفسرین نے لکھا ہے کہ ایساکرنے سے تاکید میں زیادتی ہوجاتی ہے (روح المعانی زیر آیت ھذا).کیونکہ اس میں دوچیزیں ایک فعل اورایک مصد رمقدرنکالنے پڑتے ہیں.گویاعبارت یوں ہوگی.تَعَالیٰ تَعَالِیًا وَعَلَاعُلُوًّا و ہ پا ک ہے اوربہت ہی بڑاہے اس بات سے جو یہ لوگ کہتے ہیں.یعنی خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنا قرب کسی کی معرفت دے.خودپیداکرکے پھر اپنی معرفت کے لئے روکیں پیداکرنا دانائی کے خلاف ہے.انبیاء کی آمد کی غرض بندے اور خدا کی درمیانی روک کو دور کرنا ہے اگر کوئی کہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نبی
Page 361
کیوں بھیجتا ہے اوران کامانناکیوں فرض کیا ہے ؟تواس کا جواب یہ ہے کہ نبی توصرف ا س کام کے لئے آتے ہیں کہ جوروکیں خدا تعالیٰ کی راہ میں ہوں ان کودورکیا جائے اورخدا تعالیٰ کی طرف لوگوں کومتوجہ کیا جائے.نبی خدا تعالیٰ اوربندہ کے درمیان روک بن کر کھڑانہیں ہوتا.بلکہ نبی کے باوجود ہر بندہ کاتعلق اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہوتاہے.تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ١ؕ وَ ساتو ںآسمان اورزمین اورجو ان میں (بسنے والے)ہیں اس کی تسبیح کرتے ہیں.اورجوبھی چیز ہے.و ہ اس کی اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تعریف کرتی ہوئی (اس کی )تسبیح کرتی ہے.لیکن (افسوس )تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے وہ یقیناً پردہ پوشی کرنے والا تَسْبِيْحَهُمْ١ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا۰۰۴۵ (اور)بہت (ہی)بخشنے والا ہے.حلّ لُغَات.لَاتَفْقَھُوْنَ.لَاتَفْقَھُوْنَ فَقِہَ سے مضارع کا صیغہ ہے.اورفَقِہَ الشَّیْءَ (یَفْقَہُ فِقْہًا) کے معنے ہیں.فَھِمَہُ اس کو سمجھا.وَفَقِہَ الرَّجُلُ(یَفْقَہُ)فَقَہًا کے معنے ہیں.عَلِمَ وَکَانَ فَقِیْہًا فلاں شخص عالم ہوگیا (اقرب)پس لَاتَفْقَھُوْنَ تَسْبِیْحَھُمْ کے معنے ہوں گے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے.حَلِیْمٌ.حَلِیْمٌ حَلُمَ(یَحْلُمُ حِلْمًا)سے صفت مشبّہ کاصیغہ ہے.اورحَلُمَ کے معنے ہیں صَفَحَ وَسَتَرَ درگذرکیا اورپردہ پوشی کی (اقرب)پس حَلِیْمٌ کے معنے ہوں گے.درگذر کرنے والا اورپردہ پوشی کرنے والا.تفسیر.اس آیت میں فر مایا کہ دنیا کو اگر مجموعی نظر سے دیکھا جائے تووہ بھی خداکے واحد ہونے پر دلالت کرتی ہے اوراس کی ایک ایک چیز کو دیکھاجائے تووہ علیحدہ علیحدہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خداواحد ہے.اشیاء کی تسبیح سے مراد توحید کا اقرار ہے اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ میں اس کے فرداً فرداً تسبیح کرنے کا ذکر ہے اورپہلے جملے میں مجموعی طورپر توحید ظاہر کرنے کا اشارہ ہے.ورنہ اگر تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ میں بھی فرداًفرداً توحید پردلالت کرنامقصود ہوتا توبعدمیں یہ جملہ نہ آتا.پس اس جملے کادوبارہ بیان کرنابتاتاہے کہ پہلے جملے میں دنیا کی تما م چیزوں کا مجموعی طور پر توحید ثابت کرنا ظاہر کیا گیا ہے.اور دوسرے جملے
Page 362
میں دنیا کی ہرایک چیز کا علیحدہ علیحدہ توحید کی دلیل ہونابتایا گیاہے.دنیا کی اشیاء کو دیکھ لو ایک دوسرے سے کیسی وابستہ ہیں.بعض چیزیں آپس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل پر ہوتی ہیں لیکن سب کاوجود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتاہے اورسب آپس میں ایک نظام میں منسلک ہوتی ہیں.پس ان کاایک ہی قانون سے وابستہ ہونا ظاہرکرتا ہے کہ دنیا میں کوئی دوسراقانون نہیں ورنہ ضرو رخلل ہوتا.اورجب دوسراقانون ہی نہیں تودوسرے مقنّن کاوجود کس طرح ممکن ہوگا؟ دنیاکی سب چیزیں فرداًفرداًبھی تسبیح کرتی ہیں.اس طرح کہ ہر چیز میں خدا کی صفات کی جھلک ہے.خدا کی ستاری.غفاری.اس کی خلق.اس کی ملک وغیرہ تما م صفات ہرایک چیز میں پائی جاتی ہیں یعنی وہ چیز ان باتوں پر عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے.دنیاکاکوئی ذرّہ بھی لے لو.اس میں یہ سب صفات کام کرتی نظر آئیں گی.پس جب ہرچیز خدائے واحد کی صفات کوظاہر کررہی ہے تواسے کسی اورخدا کی طرف کس طرح منسوب کیاجاسکتاہے.وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْسے بعض لوگوں نے یہ مراد لی ہے کہ ان کی علیحدہ علیحدہ بولیاں ہیں جوسمجھ میں نہیں آتیں (التفسیر البغوی زیر آیت ھذا).اگر ہرچیز کی علیحدہ بولی ہوتی اورہم اسے سمجھ نہ سکتے توہمارے لئے یہ امر دلیل کیسے بن سکتا.دلیل تووہ ہوتی ہے جسے ہم سمجھ بھی سکیں.پس یہاں پر تَفْقَھُوْنَ سے مختلف اشیا ء کی بولی سمجھنا مرادنہیں بلکہ یہ بتایا ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ تسبیح کررہی ہیں.اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا وہ حلیم و غفورہے.اس میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کے علم کی وجہ سے تم بجائے فائدہ اٹھانے کے شرارتوں میں بڑھ رہے ہو کیا تم خیال نہیں کرتے کہ ایسے نظام اوردلائل کے ہوتے ہوئے تمہاراان سے فائدہ نہ اٹھا نا بلکہ شرارتوں میں بڑھتے جانا اورفوراً نہ پکڑے جانا خدا تعالیٰ کے علم کی وجہ سے ہی ہے.پس شرافت کاجذبہ ظاہر کرو اوراللہ تعالیٰ کے پاس علم کی قدرکرو.وَ اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ اورجب توقرآن کو پڑھتاہے تو(اس وقت)ہم تیرے درمیا ن اوران لوگوں کے درمیان جوآخرت پرایمان نہیں لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًاۙ۰۰۴۶ رکھتے ایک مخفی (اورعام نظروں سے پوشیدہ )پردہ پیداکردیتے ہیں حلّ لُغَات.حِجَابًا: اَلْحِجَابُ (حَجَبَ.یَحْجِبُ)کامصدرہے.اورنیز اس کے معنے ہیں پردہ.وَکُلُّ
Page 363
مَااحْتُجِبَ بِہٖ ہروہ چیز جس کے ذریعے پرد ہ کیا جائے (اقرب) تفسیر.اس آیت کے دومعنے ہیں (۱)کہ جب توقرآن شریف پڑھتا ہے توہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جوآخرت پرایمان نہیں لاتے ایک ایساپردہ ڈال دیتے ہیںکہ وہ پردہ خود بھی چھپاہواہوتاہے.یعنی وہ حجا ب بھی ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتاہے.یہ اس لئے فرمایاتاکوئی بے سمجھ حجاب کے لفظ سے ظاہری پردہ نہ سمجھ لے.آنحضرت ؐ اور مخالفین کے درمیان حجاب کی تشریح بعض لوگوں نے پردہ سے ایسا پردہ مراد لیا ہے.کہ جس سے نبی کریم صلعم چھپ جاتے تھے اورانہوں نے زوجہ ابولہب کاقصہ لکھا ہے.کہ جب سورۃ اللہب اتری تو فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍسن کر وہ غصہ میں بھری ہوئی نبی کریم صلعم کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے لپکی.نبی کریم صلعم نے دعاکی کہ الٰہی !تومجھے اس کے شرسے بچالے.تو خدا تعالیٰ نے آپ کے آگے پردہ حائل کردیا اوراس وجہ سے وہ آپ کودیکھ نہ سکی(تفسیر کبیر لامام رازی سورۃ اللھب زیر آیت فی جیدھا حبل..).یہ محض خرافات ہیں.خدا کاو ہ رسول جو ساری دنیا سے نہ ڈرا.ا س کمزور عورت سے اس قدر خائف ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کو اسے غائب کرنا پڑا.اس غیر معقول بات کو کوئی عقلمند تسلیم نہیں کرسکتا.اس روایت کو پیش کرنے والے یہ بھی نہیں سوچتے.کہ خدا تعالیٰ تواس حجاب کو مَسْتُوْر قرار دیتاہے یعنی و ہ پردہ نظر نہیں آتا.مگریہ لوگ پردے کو ظاہرکرکے نبی کریم صلعم کو مستور قراردیتے ہیں.(۲)دوسرے معنے اس جملہ کے یہ ہوسکتے ہیں.وہ پرد ہ بھی آگے ایک اَورپردے کے پیچھے ہوتاہے.یعنی ایک پردہ ہی تیرے اور ان کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ کئی پردے حائل ہوتے ہیں.کوئی پردہ قومی غیرت کا.کوئی مال کا.کوئی اخلاق کا وغیرہا.وغیرہا.یعنی کبھی لو گ اس خیال سے ایمان نہیں لاتے کہ اس کوماناتوقوم چھوڑ نی پڑے گی.کبھی یہ خیال حائل ہو جاتا ہے.کہ ما ل جاتارہے گا.کبھی یہ بات راستہ روک کر کھڑی ہوجاتی ہے کہ کئی قسم کے بداخلاق جن کی عادت پڑی ہوئی ہے چھوڑنے پڑیں گے.پس اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جب تک یہ لوگ ان پردوںکو نہ ہٹائیں گے تجھ تک نہ پہنچ سکیں گے.مگر مصیبت یہ ہے کہ و ہ پرد ے ایسے ہیں کہ ان کونظر نہیں آتے.ان کی نظروں سے پوشید ہ ہیں.وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآ ن کریم ہی بُری چیز ہے.اگر وہ اچھی چیز ہوتی توجلدی ہی ہمارے دلوں پر اس کی قبولیت کا اثرہوجاتا.گویاان کے دلوں پر ایسے زنگ ہیں کہ ان کواچھی چیز بری لگتی ہے.اور بری چیز اچھی لگتی ہے.اس لئے ایمان کانصیب ہو نا مشکل ہورہاہے.ان معنوں کی تصدیق اگلی آیت وَجَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِھِمْ اَکِنَّۃً سے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں پر ایک پرد ہ نہیں بلکہ کئی پردے ہیں.
Page 364
وَّ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ اورہم ان کے دلوں پر (بھی)کئی پردے ڈال دیتے ہیں تاوہ اس(سچائی کے انکار کی حقیقت)کو سمجھیں اوران کے وَقْرًا١ؕ وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى کانوں میں بہرہ پن ہے.اورجب توقرآن میں اپنے رب کو جو ایک ہی ہے یاد کرتاہے توو ہ نفرت سے اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا۰۰۴۷ (تیری طرف ) اپنی پیٹھیں پھیر کرچلے جاتے ہیں.حلّ لُغَات.اَکِنَّۃ اَلْاَکِنَّۃُ.اَلْکِنُُّّ کی جمع ہے.اوراَلْکِنُّ کے معنے ہیں وِقَاءُ کُلِّ شَیْءٍ وَسِتْرُہُ ہرچیز کے اوپر کاپر دہ جواس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے.(اقرب).وَقْرًا وَقْرًا وَقَرَ (یَقِرُ)سے ہے اور وَقَرَتْہُ اُذُنُہٗ کے معنے ہیں.ثَقُلَتْ اَوْ ذَھَبَ سَمْعُہٗ کُلُّہٗ وَصَمَّتْ اس کے کان بوجھل ہوگئے یااس کی شنوائی جاتی رہی اورکا ن بہر ے ہوگئے.(اقرب)پس وَقْر کے معنے ہوں گے.بہراپن.کان کابوجھ.وَلَّوْا وَلَّوْا وَلّٰی سے جمع کاصیغہ ہے.اوروَلّٰی ھَارِبًا کے معنے ہیں اَدْبَرَ پیٹھ دے کربھاگ گیا.وَلَّی الشَّیْءَ وَعَنِ الشَّیْءِ.اَعْرَضَ وَنَاٰی.اس نے کسی سے اعرا ض کیااورپہلوتہی کی (اقرب)پس وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ کے معنے ہوں گے کہ وہ پیٹھ پھیر کربھاگ جاتے ہیں.تفسیر.اَنْ یَّفْقَھُوْہُ محذوف مفعول لہ کامتعلق ہے.اورمرادیہ ہے کہ اس کراہت کی وجہ سے ہم نے پردے ڈال دئے ہیں کہ ایسے گندے لوگ جنہوںنے اپنے دلوں کومختلف ظلمتوں میں چھپارکھا ہے.اسلام میں داخل ہوکر اس کی بدنامی کاموجب نہ ہو ں.اس اعتراض کا جواب کہ جب پردے خدا نے ڈالے ہیں تو بندوں کا کیا قصور اس پر اعتراض ہوسکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے ہی پردے ڈال دئے ہیں تووہ کیسے سمجھیں اوران پرالزام کیسا؟تواس کا جواب دوسری جگہ بطور اصو ل کے بیان فرما دیا ہے.اوروہ یہ ہے.وَمَایُضِلُّ بِہٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِیْنَ(البقر ۃ :۲۷)کہ اس قسم کے
Page 365
پردے انسان کے اپنے نفس سے ہی پیدا ہوتے ہیںکوئی باہر سے نہیں آتے.تیسر ی جگہ فرمایا.اَمْ عَلیٰ قُلُوْبٍ اَقْفَالُھَا( محمد:۲۵)کہ ان کے دلوں پرقفل ہیں جو ان کے دلوںسے ہی پیداہوئے ہیں.پس انسان ہی اپنے لئے پردے اورقفل تجویز کرتاہے اوراللہ تعالیٰ ا س کے اپنے تجویز کئے ہوئے پردوں کو اس کے دل پرڈال دیتا ہے.کیونکہ جب تک دل صاف نہ ہو.الٰہی سلسلہ میں داخل ہونے والے کوتوکوئی نفع ہوتانہیں.الٰہی سلسلہ مفت میں بدنام ہو جاتا ہے.وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰۤى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا اس میں’’ وَحْدَہٗ‘‘کالفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ مشرک لوگ خدا تعالیٰ کوتومانتے ہیں لیکن توحید سے انہیں چڑ ہوتی ہے.یہ بھی پردوں میں سے ایک پردہ ہے.نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖۤ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَ اِذْ (اور)جب و ہ(بظاہر)تیری باتیں سن رہے ہوتے ہیں توجس غرض سے وہ سن رہے ہوتے ہیںاس (کی حقیقت ) هُمْ نَجْوٰۤى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا کوہم (سب سے )زیادہ جانتے ہیں اور(نیز اس کی حقیقت کو بھی)جب وہ باہم سرگوشی کررہے ہوتے ہیں (اور)جب مَّسْحُوْرًا۰۰۴۸ وہ ظالم (ایک دوسرے سے )کہہ رہے ہوتے ہیں (کہ )تم ایک فریب خوردہ شخص ہی کی پیر وی کررہے ہو.حلّ لُغَات.یَسْتمعون.یَسْتَمِعُوْنَ اِسْتَمَعَ سے جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے اوراِسْتَمَعَ لَہُ وَاِلَیْہِ کے معنے ہیں اَصْغٰیاس نے اس کی طرف کان لگاکر بات سنی (اقرب) نَجوٰی.نَجوٰیکے معنے ہیں اَلسِّرُّ.بھید.اَلْمُسَارُّوْنَ.راز کی باتیں کرنے والے.وَھُوَ وَصفٌ بِالْمَصْدَرِ یَسْتَوِی فِیْہِ الْمُفْرَدُ وَالْجَمْعُ.نجوی مصدر ہے جوبطور صفت بیان ہواہے.اس لئے مفرداورجمع دونو طرح استعمال ہوسکتا ہے.(اقرب)پس اِذْ هُمْ نَجْوٰۤى کے معنے ہیں کہ جب و ہ باہم سرگوشی کررہے ہوتے ہیں.مَسْحُور.مَسْحُورُکے معنے جس کو دھوکہ دیا گیاجس کو کسی چیز سے روکا گیا.جس کی عقل ماری گئی.مسلول.ان سب معنوں کے لحاظ سے اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا کے یہ معنے ہوں گے کہ تم نہیں اتبا ع کرتے مگراس کی
Page 366
جودھوکہ خورد ہ ہے یاسچائی سے پھیراگیاہے یا جس کی عقل ماری گئی ہے یالاعلاج بیماری میں مبتلا ہے.قوم کی حالت کے غم میں انبیاء کی صحت عموماًاچھی نہیں رہتی.اس لئے و ہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کمزور اوربیمار ہے یونہی چند یوم کاشورہے.تھوڑے ہی دن میں مرجائے گا.تفسیر.اس آیت میں بِہٖ کی بَاء لام کے معنوں میں ہے اورمطلب یہ ہے کہ ہم اس امر کو خوب جانتے ہیں جس کی خاطریہ تیری باتیں سنتے ہیں یعنی یہ صرف انکارو الزام کی خاطرسنتے ہیں.ان الفاظ میں وَقر کی تشریح کی گئی ہے.بہٖ میں با مصاحبت کی بھی ہوسکتی ہے.کہ جس چیز کے ساتھ و ہ سنتے ہیں اس کوہم جانتے ہیں یعنی سنتے وقت جوحالت ان کے دل کی ہوتی ہے ہم اس سے واقف ہیں.وہ قلبی حالت کیا ہے ؟ وہ استہزاء اور مخالفت کے خیالات ہیں جو سنتے وقت ان کے دلوں میں پیداہورہے ہوتے ہیں.آیت میں چند اَورپردوں کا ذکر کیا گیا ہے فرماتا ہے کہ ایک توشرک ان کے رستہ میں روک ہے.دوسراپردہ یہ ہے کہ یہ غورسے بات سنتے ہی نہیں.الزام لگانے اور تمسخر کرنے کے خیال سے سنتے ہیں.جب دل کی یہ حالت ہوتو بات سمجھ کس طرح آئے.تیسر ا پردہ ان کے دل پر یہ پڑاہواہے کہ محمد رسولؐاللہ کو کمزور سمجھتے ہیں اورخیال کرتے ہیں کہ زیادہ دن تک یہ بات نہیں چلاسکتا.پھر اسے مان کر کیوں ذلیل ہوں.چوتھاپردہ یہ ہے کہ بعض نادان محمد رسولؐ اللہ کودیوانہ خیال کرتے ہیں.ا س لئے آپ کی بات سن کر توجہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے.پانچواں پردہ یہ ہے کہ بعض خیا ل کرتے ہیں کہ اسے دھوکا لگ گیاہے اورو ہ اس خیال میں خوش ہیں کہ ہم نے اس کی حقیقت معلوم کرلی ہے اورغور اورفکر سے آزاد ہوگئے ہیں.اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ جب و ہ مسلمانوں پر ظلم کرتے کرتے تھک گئے اوراس طر ح کامیابی نہ ہوئی تو وہ چھپ چھپ کرلوگوں کوسمجھا نے لگے اورنرمی کاپہلو اختیار کرکے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ ہونے کی تلقین کرنی شروع کردی.
Page 367
اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ دیکھ انہوں نے تیرے متعلق کس طرح باتیں بنائی ہیں.جس کے نتیجہ میں و ہ گمراہ ہوگئے ہیں اور(اب ) سَبِيْلًا۰۰۴۹ و ہ(اس گناہ سے بچنے کی ) کوئی راہ نہیں پاسکتے.تفسیر.اس آیت میں اَمْثَال (جمع کالفظ )رکھ کربتادیا کہ اوپر کی آیت میں مَسْحُور کے سارے ہی معنے مراد تھے ورنہ مَثَل کالفظ چاہیے تھا.اس سے یہ بھی معلو م ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے جوالفاظ کئی معنے رکھتے ہیں جب و ہ سیاق و سباق سے مناسبت رکھتے ہوں توسب کے سب معنے بیک وقت مراد ہوتے ہیں.وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ۠ خَلْقًا اورانہوں نے (یہ بھی )کہا ہے (کہ )کیا جب ہم (مر کر)ہڈیاں اور چُوراچُوراہوجائیں گے (توہمیں از سرنوزندہ کیا جَدِيْدًا۰۰۵۰ جائے گااور)کیا واقعی ہمیں ایک نئی مخلوق کی صور ت میں اٹھایاجائے گا.حلّ لُغَات.عِظَامًا.اَلْعِظَامُ اَلْعَظْمُ کی جمع ہے اوراَلْعَظْمُ کے معنے ہیں.ہڈی (اقرب) رُفَاتًا اَلرُّفَاتُ کے معنے ہیں اَلْحُطَامُ سوکھی ہوئی چیز کے ٹکڑے.کُلُّ مَاتَکَسَّرَ وَبَلِیَ.بوسید ہ اور چورا چیز (اقرب) تفسیر.پیچھے ذکر ترقیات کاتھا اورپھر کفار کے جہنم میں گرائے جانے کا ذکر تھا.اس کے متعلق جو کفار کو شبہ پیداہوسکتا تھا اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیاہے فرماتا ہے کفاران باتوں کوسن کر اعتراض کرتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاںاو رریزہ ریزہ ہوجائیں گے توکیاپھر ہماری نئی پیدائش ہوگی.
Page 368
قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًاۙ۰۰۵۱اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ تو(انہیں )کہہ(کہ )تم (خواہ)پتھر بن جائو یالوہا.یاکوئی اورایسی مخلوق جوتمہارے دلوں میں عظمت رکھتی ہو فِيْ صُدُوْرِكُمْ١ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ۠ مَنْ يُّعِيْدُنَا١ؕ قُلِ الَّذِيْ (تب بھی تم کو دوبار ہ زندہ کیا جائے گا)اس پر وہ ضرور کہیں گے (کہ )کو ن ہمیں دوبارہ (زندہ کرکے وجود میں ) فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ١ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ۠ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَ لائے گاتو(انہیں )کہہ(کہ)وہی جس نے تمہیں پہلی با رپیدا کیاتھا.اس پر وہ لازماً تعجب سے تمہاری طرف يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ١ؕ قُلْ عَسٰۤى ( دیکھتے ہوئے )اپنے سرہلائیں گے اورکہیں گے (کہ)وہ (از سرنوزندہ کیاجانا)کب ہوگا (جب وہ ایساکہیں اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا۰۰۵۲ تو)تو(ان سے )کہہ(کہ)بالکل ممکن ہے کہ وہ (وقت اب)قریب (آچکا)ہو.حلّ لُغَات.فَسَیُنْغِضُوْنَ:فَسَیُنْغِضُوْنَ اَنْغَضَ سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے اور اَنْغَضَ فُلَانٌ رَاْسَہٗ کے معنے ہیں حَرَّکَہٗ کَالْمُتَعَجِّبِ مِنَ الشَّیْءِ اپنے سرکوحرکت دی جیسے کو ئی متعجب سر کو حرکت دیتاہے (اقرب)پس فَسَیُنْغِضُوْنَ اِلَیْکَ رُءُ وْ سَہُمْ کے معنے ہوں گے کہ و ہ تمہاری طرف اپنے سرکو ہلائیں گے.تفسیر.پہلی آیت میں جواعتراض پیش کیاگیاتھا اس کے جوا ب میں فرماتا ہے کہ تمہارے اندرکتنا ہی تغیر آجائے.پتھر ہوجائو یا لوہا یااس سے بھی بڑی کوئی چیز توبھی تم خدا کی سزاسے بچ نہیں سکتے.یااس کے معنے یہ ہیں کہ تم اپنے دلوں کوکتناہی سخت بنالو.پھر بھی ہمارے رسول کی ترقی ضرور ہوگی.تم میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوجائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حشر برپا کردے گا.ممکن ہے کہ انسانی جسم زمین میں ایک لمبا عرصہ تک مدفون ہو کر پتھر بن جائے میں اس آیت
Page 369
سے نتیجہ نکالتاہوں کہ ممکن ہے انسانی جسم میں لمبے عرصہ کے بعد ایساتغیر پیداہوجاتا ہو کہ وہ کسی دوسرے مادہ کی شکل میں تبدیل ہوجاتا ہو.سائنس کی تحقیقات سے توثابت ہے کہ کئی درخت جو کسی وقت زمین میں د ب گئے تھے.تغیرات زمانہ کے بعد پتھر کاکو ئلہ بن گئے(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ coal).اسی طرح یہ کہ ہیراکوئلہ سے ہی بناہے.پس یہ تعجب کی بات نہیں.کہ انسانی جسم مرنے کے بعدزمین میں ایک لمباعرصہ دفن رہنے پرپتھر بن جائے گوابھی تک آثار قدیمہ سے ایساکوئی نشان نہیں ملا.مگر یہ عقل کے خلاف نہیں.پس میرے نزدیک اس جملہ سے اس طرف اشارہ کیا گیاہے کہ خواہ انسانی دورحیات پرلاکھو ں کروڑوں سال کاعرصہ گزر جائے جس سے انسانی اجزاء کی جو زمین میں دفن ہیں شکل ہی تبدیل ہوجائے تب بھی انسان دوبار ہ بعث سے نہیں بچ سکتا بعث ضرو ر ہوگا.مَنْ يُّعِيْدُنَاسے یہ مراد نہیں کہ وہ سنجید گی سے سوال کرتے ہیں.کہ انہیںکون پیداکرے گا بلکہ یہ تمسخر ہے کہ دکھلائو تو سہی جوکہتاہے کہ ایساہوگا.جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ذرااس کامنہ تودکھلائو جوایساکرنے کادعویدار ہے مطلب ا س سے صرف انکار ہوتا ہے.فَسَيُنْغِضُوْنَ۠ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ.اَنْغَضَ فُلَانٌ رَاْسَہُ:حَرَّکَہُ کَالْمُتَعَجِّبِ مِنَ الشَّیْءِ.یعنی سرکوہلایا ایسے انسان کی طر ح جوکسی بات سے تعجب کررہا ہے.اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سرہلاہلاکر تمسخرانہ رنگ میں باتیں کریں گے اورکہیں گے اچھا یہ بات ہے ؟اب ہم سمجھے.حشر سے مراد تمام عرب کا مسلمان ہونا ہے عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا.اس میں یہ بتایا ہے کہ جس حشر کا ہم اس سورۃ میں ذکرکررہے ہیں وہ وہ نہیں جس پر تم اعتراض کرتے ہو ہماری مراد اس سور ۃ میں اس حشر سے ہے جومسلمانوں کے ذریعہ سے اس دنیا میں ہونے والا ہے اوربتایا ہے کہ وہ حشر جس کا ہم نے یہاں ذکر کیاہے وہ توبس قریب ہی ہے.چنانچہ اس کے کچھ عرصہ بعد عرب کے لوگ مسلمان ہوگئے.اوراس سورۃ میں جس حشر کی خبر تھی و ہ ظاہر ہوگیا.
Page 370
يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَ تَظُنُّوْنَ اِنْ (یہ وعدہ اس د ن پوراہوگا)جس دن وہ تمہیں بلالے گاتوتم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کاحکم مانو گے (اورفوراً لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًاؒ۰۰۵۳ حاضر ہوگے)اور تم سمجھ رہے ہو گے کہ تم (دنیا میں )تھوڑاہی ٹھیرے تھے.تفسیر.اس آیت نے ظاہرکردیا کہ وہ حشر جس کایہاں ذکر ہے.اسی دنیا میں ہوگا.چنانچہ فرماتا ہے کہ حشر اس دن مقر ر ہے جبکہ تم کو خدا تعالیٰ یااس کارسولؐ بلائے گااور تم مردوں کی طرح خاموش نہیں رہوگے جس طرح آج خاموش ہو.بلکہ اس دن تم میں سے اکثر محمد رسول اللہؐ کی بات پرلبیک کہتے ہوئے دوڑ پڑیں گے اورتسبیح کرنے لگیں گے اوراس وقت تم حیران ہو گے کہ خواہ مخواہ ہم اسلامی ترقی کے ظہور کے زمانہ کو لمباسمجھتے رہے.اسلامی ترقی کا زمانہ توبڑی جلدی آگیا.یہ بھی معنے ہوسکتے ہیں کہ جب لو گ ایمان لائیں گے اپنی کفر کی زندگی کو بہت حقیر سمجھیں گے.اور سمجھیں گے کہ اصل پیدائش توہماری اب ہوئی ہے.اسی طرح مومن بھی تکالیف کے ایام کو بھول جائیں گے.اورسمجھیں گے کہ یہ دن توآنکھ جھپکتے گذر گئے.غرض آیت میں زمانہ کی لمبائی کا ذکر نہیں بلکہ ان احساسات کا ذکر ہے جواس وقت پیداہوں گے.ایک حدیث میں آتاہے کہ لَیْسَ عَلٰی اَھْلِ لَااِلٰہَ اِلَّا اللہُ وَحْشَۃٌ فِی قُبُوْرِھِمْ وَلَافِی مَنْشَرِھِمْ وَکَاَنِّیْ بِاَھْلِ لَااِلٰہَ اِلّااللہُ یَنْفَضُوْنَ التُّرَابَ عَنْ رُؤُ وْسِہِمْ وَیَقُوْلُوْنَ اَلْحَمْدُ لِلہِ الَّذِیْ اَذْھَبَ عَنَّا الْحُزْنَ(روح المعانی زیر آیت ھذابحوالہ ترمذی وطبری و معجم ) کہ لَااِلٰہَ اِلَّا اللہُ کہنے والوں کوقبر میں اور حشر میں بھی آرام ہی رہے گا.اوران کی وہ حالت گویا میں اب دیکھ رہاہوں جبکہ وہ حشر کے دن اٹھیں گے اوراپنے سر سے مٹی جھاڑ رہے ہوں گے اوریہ کہتے جاتے ہوں گے کہ اللہ کاشکر ہے جس نے ہرقسم کے غم ہم سے دور کردئے.گویاراحت اورترقی کے ملتے ہی سب غم و حزن دور ہوجائیں گے اوراس زمانہ کووہ نہایت مختصرخیال کرنے لگیں گے.
Page 371
وَ قُلْ لِّعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ١ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ اورتومیرے بندوں سے کہہ(کہ)وہ وہی بات کہا کریں جو (سب سے )زیادہ اچھی ہو يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ١ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا (کیونکہ)شیطان یقیناًان کے درمیان فساد ڈالتاہے.شیطان انسان مُّبِيْنًا۰۰۵۴ کا کھلا (کھلا )دشمن ہے.حلّ لُغَا ت.یَنْزَغُ:یَنْزَغُ نَزَغَسے مضارع واحد مذکر غائب کاصیغہ ہے.اورنَزَغَ کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۱۰۱.نَزَغَہُ: طَعَنَ فِیْہِ.نزغ کے معنے ہیں طعنہ زنی کی.اِغْتَابَہُ کسی کی غیبت کی.وَذَکَرَہُ بِقَبِیْحٍ.اور اس کے متعلق بدگوئی کی.اور نَزَغَ بَیْنَ الْقَوْمِ کے معنی ہیں اَغْرٰی وَاَفْسَدَ وَحَـمَلَ بَعْضَہُمْ عَلٰی بَعْضٍ.کہ قوم کے درمیان بگاڑ و فساد ڈالا اور ایک کو دوسرے کے خلاف برانگیختہ کیا.اور نَزَغَ الشَّیْطٰنُ بَیْنَہُمْ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کے درمیان بگاڑ ڈال دیا.(اقرب) تفسیر.باوجود سورتوں کے آگے پیچھے نازل ہونے کے پھر بھی مضامین میں ترتیب ہے قرآن کریم کو پڑھ کر کیاہی لطف آتاہے ایک سورۃ پہلے نازل ہوئی ہے اوردوسری سورۃبعد میں.پھر پہلی کوترتیب میں بعد میں رکھ دیاگیا ہے اوربعد والی کو پہلے.لیکن ان کے مضمو ن اس طرح ایک جا ن ہوجاتے ہیں جیسے کہ ایک وقت میں لکھی ہوئی کتاب کے دوباب.سورۃ النحل میں فرمایا تھا.اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ (النحل:۱۲۶).اسی ترتیب کے مطابق سور ۃ بنی اسرائیل کوشروع کیاگیاہے.چنانچہ قرآن پاک کی تعلیمی خوبیوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا.ذٰلِکَ مِمَّآاَوْحٰٓی اِلَیْکَ رَبُّکَ مِنَ الْحِکْمَۃِ(بنی اسرائیل:۴۰)کہ یہ حکمت کی باتیں ہیں.اس کے بعد وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰہِ اِلٰھًا اٰخَرَ سے کلام شروع کیا اورالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ والی شق کو پوراکیا.طریق گفتگو کے متعلق نرمی کی تاکید تیسری بات یہ فرمائی تھی وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ.اس کا جواب
Page 372
اب قُلْ لِّعِبَادِيْ سے شروع فرمایا.اس ترتیب کو دیکھ کر کوئی شخص کیونکر کہہ سکتاہے کہ قرآن کریم میں کوئی ربط نہیں ہے.اس آیت میں نصیحت کی گئی ہے کہ نہایت سوچ سمجھ کر کلام کیاکرو اور دوسرے لوگوں سے ایسے رنگ میں گفتگو کروجس سے ان کے دلوں پر اچھا اثر ہو.اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو تواپنے دوستوں سے بھی اچھی بات کرنی چاہیے.لیکن جبکہ دشمن دوسرے لوگوں کے دلوں میں نفرت اورعداوت پیداکررہاہو.تب تواوربھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے.پس ایسے طریق سے کلام کرو اورگفتگو میں ایسی راہ اختیار کروجودوسروں کوبھی نرم کرلے.شیطان سے بدکردار انسان بھی مراد ہوسکتے ہیں اوروہ مخصوص ہستی بھی.کیونکہ وسوسہ اندازی اس کاکام ہے.اس آیت میں یہ بھی اشا رہ کیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہوکہ یَوْمَ یَدْعُوْکُمْ والی بعثتِ اسلامی جلد ظہور پذیر ہو تو ایساطریق اختیارکرو کہ یہ لوگ جلد مسلمان ہو ں.اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ تَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ سے اسلام قبول کرنا ہی مراد ہے.رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ١ؕ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَّشَاْ تمہارارب تمہیں(سب سے )زیادہ جانتا ہے اگر وہ چاہے گاتوتم پر رحم کرے گااوراگر وہ چاہے گاتوتمہیں عذاب يُعَذِّبْكُمْ١ؕ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا۰۰۵۵ دے گا اور(اے رسول )ہم نے تجھے ان کاذمہ وار بناکرنہیں بھیجا.تفسیر.فرمایاہم ہی انسان کی دونو حالتوں کو جاننے والے ہیں.نیکی کی حالت کو بھی اوربدی کی حالت کو بھی اوردل کاحال ہمارے سواکوئی نہیں جانتا.اس لئے ہم نے جزاسزاکامعاملہ اپنے ہاتھ میں رکھاہواہے اَورکسی کے ہاتھ میں نہیں دیا.حتٰی کہ رسول اللہ کے سپرد بھی نہیں کیا.پس جیسے جیسے تمہاری حالتیں بدلتی جائیں گی ہمارامعاملہ بھی بدلتاجائے گا.
Page 373
وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا اورجو(کوئی بھی )آسمانوں اورزمین میں (بسنے والے )ہیں انہیں تمہارارب(سب سے )زیادہ جانتاہے اورہم بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا۰۰۵۶ نے یقیناً انبیاء میں سے بعض کو بعض (دوسر ے انبیا ء )پر فضیلت دی ہے اوردائود کو(بھی)ہم نے ایک زبور دی تھی تفسیر.پہلی آیت میں انبیاء کے مخاطبین کو جاننے کا ذکرفرمایاتھا اب ا س آیت میں فرماتا ہے جس طرح ہم ان کو جانتے ہیں اسی طرح انبیاء کو بھی جانتے ہیں خواہ آسمان پر ہوں یعنی وفات یافتہ ہوں یازمین پرہوں یعنی زندہ ہوں.یادوسرے لفظوں میں یہ کہ محمدرسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی خوب جانتے ہیں اوراس سے پہلے کے نبیوں کو بھی.اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کس زمانہ میں کیسے نبی کی ضرورت ہوتی ہے اوراسی خیال سے ہم نے انبیاء کے بھی مدارج مقر رفرمائے ہیں.تاکہ ہرزمانہ کی ضرورت کے مطابق نبی آئے.ان انبیاء میں سے دائود علیہ السلام کا ذکرالگ بھی بیان فرمایا ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کے ذکر میں ان کے دوعذابوں کا ذکرفرمایاتھا.ایک حضرت دائود کے بعد جب کہ یہود میں دولت بہت ہوگئی اورتعیّش پیداہوگیا.اور دوسرے حضرت مسیح ؑ کے بعد ان کے انکار کی وجہ سے.چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مثیل موسیٰ ہیں جیساکہ فرمایا.اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (المزمل:۱۶)ہم نے تم پر گواہ بناکر تمہارے اندر اپنا رسول بھجوایا ہے اوریہ بعثت ویسی ہی ہے جیسا کہ فرعون کی طرف موسیٰ ؑ کی بعثت تھی.اورتورات میں ایک مثیل موسیٰ کی خبردی گئی تھی.استثناء باب ۱۸آیت ۱۸.اوراس کے مقابل پر امت محمدیہؐ کے مثیل بنی اسرائیل ہونے کی خبر سورۃ فاتحہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دی گئی تھی.اس لئے اسی مشابہت کی بناء پر حضرت دائود کانام مسلمانوں کونصیحت کرتے وقت خاص طورپرلیا.تاانہیںتوجہ دلائی جائے کہ اے مسلمانوں!ترقی اورکامیابی کے وقت دائود کاواقعہ یاد رکھنا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ جس طرح دائود کے زمانہ میںیہود نے دنیوی ترقیات سے فائدہ کی بجائے نقصان اٹھایا.اوردین سے غافل ہوگئے.تم بھی کہیں ایسا نہ کرنا اوراس وقت کوخوف اورخشیت سے گذارنا.امت محمدیہ کی مماثلت بنی اسرائیل سے باوجوداس انذارکےمسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے
Page 374
ہی عرصہ کے بعد بگڑے جتنے عرصہ کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے بعد بگڑے تھے.اورگو اس وقت ان میں دائود کی طرح نبی نہیں آیا لیکن ایسے نیک بادشاہ ضرور پیداہوئے جنہوں نے حضرت دائودؑ اورسلیمانؑ کی طرح نیکی کانمونہ دکھایا.مگراس وقت دولت کے نشہ میں سرشار تھے اوراسلام کی خدمت سے غافل ہورہے تھے.چنانچہ قریباً اتنا ہی زمانہ گذرنےپرجتناحضرت موسیٰ اوریروشلم کی تباہی پر گذراتھا.بغداد ہلاکو خان کے ہاتھ سے تباہ ہوگیا.اوراسلامی شوکت مٹ گئی.جس کے بعد اسے کبھی پوری شان کے ساتھ قائم ہونے کاموقعہ نہیں ملا.قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ تو(انہیں )کہہ(کہ)اس کے سواجن لوگوں کے متعلق تمہارادعویٰ ہے (کہ و ہ الوہیت رکھتے ہیں )انہیں (اپنی مدد فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ کے لئے بھلا) پکارو(تو).پس (تمہیں معلوم ہوجائے گا کہ)نہ وہ (تمہاری کسی )تکلیف کو تم سے دور کرنے کا وَ لَا تَحْوِيْلًا۰۰۵۷ اختیاررکھتے ہیں اورنہ (تمہاری حالت میں )کوئی تبدیلی پیداکرنے کا.حلّ لُغَات.زعمتم.زَعَمْتُمْ زَعَمَ سے جمع مخاطب کاصیغہ ہے.اورزَعَمَ الرَّجُلُ (یَزْعُمُ) کے معنے ہیں قَالَ قَوْلًا حَقًّااس نے سچی بات کہی وَکَذَا بَاطِلًا وَکِذْبًا(ضِدٌّ) چونکہ یہ لفظ اضداد میں سے ہے اس لئے اس کے معنے جھوٹی بات کرنے کے بھی ہیں.وَاَکْثَرُ مَا یُقَالُ فِی مَایُشَکُّ فِیْہِ اَوْ یُعْتَقَدُ کِذْبُہٗ ا ورا س کااکثر استعمال ان باتوں میں ہوتاہے جن میں شک و شبہ ہو یا اس کے جھو ٹ ہو نے پر یقین ہو(اقرب) فلا یَمْلکُونَ.فَلَا یَمْلِکُوْنَ مَلَک سے مضارع جمع کاصیغہ ہے اورمَلَکَ کے لئے دیکھو رعدآیت نمبر ۱۷.مَلَکَ کے معنے ہیں اِحْتَوَاہُ قَادِرًا کسی چیز پر قادرانہ طور پر قبضہ کیا.مَلَکَ عَلی الْقَوْمِ: اِسْتَوْلٰی عَلَیْہِمْ کسی قوم پر غالب ہوا.عَلٰی فُلَانٍ اَمْرَہُ.کسی کے کام کا متولی ہوا.اَلْخِشْفُ أُمَّہٗ :قَوِی وَقَدَرَ اَنْ یَتْبَعَہَا.ہرن کا بچہ توانا و مضبوط ہوکر اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنی ماں کے پیچھے چل سکے.(اقرب) پس لَا يَمْلِكُوْنَ کے معنے ہوں گے وہ قادر نہیں ہوسکتے.وہ طاقت نہیں رکھ سکتے.
Page 375
کشفٌ:کَشْفٌ کَشَفَ (یَکْشِفُ) کامصدر ہے اورکَشَفَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں اَظْھَرَہُ وَرَفَعَ عَنْہٗ مَا یُوَارِیہِ وَیُغَطِّیْہِ.کسی چیز سے پرد ہ ہٹا کراسے ظاہر و ننگا کردیا.کَشَفَ اللہُ غمَّہٗ.اَ زَالَہ ٗ.اللہ تعالیٰ نے اس کے غم کو دور کردیا (اقرب).اَلضُّرُّ.اَلضُّرُّکے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر۸۹.اَلضُّرُّ: ضِدُّ النَّفْعِ.ضر کے معنے ہیں نقصان.سُوْءُ الْحَالِ وَالشِّدَّۃُ.تنگ حالی وَفِی الْکُلِّیَّاتِ الضَّرُ بِالْفَتْحِ شَائِعٌ فِی کُلّ ضَرَرٍ وَبِالضَّمِّ خَاصٌ بِمَا فِی النَّفْسِ کَمَرَضٍ وَھُزَالٍ کلیات میں یوں لکھا ہے کہ ضَرٌّ کے معنے خاص اس تکلیف کے ہیں جو خود نفس میں ہو جیسے بیماری یا لاغر پن وغیرہ لیکن ضُرٌّ کا لفظ عام ہے اور ہر تکلیف پر بولا جاتا ہے.(اقرب) تَحْویْلًا تَحْوِیْلٌ حَوَّلَ کامصدر ہے یہ لفظ لازم اور متعدی دونوں طرح پراستعمال ہوتاہے.حَوَّلَہٗ (متعدی) نَقَلَہٗ مِنْ مَوْضِعٍ اِلٰی اٰخَرَ اسے ایک جگہ سے دوسر ی جگہ منتقل کردیا.حَوَّلَ الشَّیْءَ اِلَیْہِ :قَلَّبَہٗ واَ زَالَہٗ کسی چیز کو کسی اورصورت میں تبدیل کردیا.حوَّلَ ھُوَ.(لازم) اِنْتَقَلَ کوئی چیز اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلی گئی.(اقرب) تفسیر.حشر ارواح پچھلی تین چار سورتوںمیںیہ مضمون بیان ہواتھاکہ کفار حشر اسلام کی آیات سن کر یہ دھوکاکھاجاتے ہیں کہ شاید اس سے حشر اجساد مراد ہے اوراس پر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں.لیکن وہ بھی مراد ہوتب بھی ان کااعتراض درست نہیں.لیکن اس موقعہ پر حشر اجساد کا ذکر نہیں بلکہ حشرارواح کا ذکر ہے.اوریہ ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت پر اپنے بندوں کو آواز دے گا توآئمہ کفار کے بنے ہو ئے جال ٹو ٹ کر تاگہ تاگہ ہوجائیں گے اوران کے شکار ان میں سے نکل کر محمد رسول اللہ صلعم کی طرف چلے جائیں گے.پھر مسلمانوں کو اس ترقی کے زمانہ میں ہوشیار رہنے کاحکم دیاتھا.اب پھر پہلے مضمون کی طرف رجوع فرماتا ہے اورکفار سے خطاب فرماتا ہے کہ یہ جومسلمانوں کی ترقی اور تمہاری ہلاکت کی پیشگوئی کی گئی ہے اسی سے اپنے دین کی سچائی اور شرک کی حقیقت کا پتہ لگا لو.ہم کہتے ہیں کہ تم پرعذاب آئے گا تم اپنے معبودوں سے دعائیں کرکے دیکھو کہ کیا وہ تمہاری دعائیں سن سکتے ہیں اورعذاب کوہٹاناتو الگ رہا.کیااسے کچھ عرصہ کے لئے ملتوی کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں.چونکہ آئندہ تباہی شرک سے ہونے والی تھی اس لئے اس کی تفصیل بتائی ہے.مسلمانوں میں بھی بغداد کی تباہی
Page 376
کے وقت شرک ہی پیداہوگیاتھا.مسلمانوں نے فتوحات کے زمانہ میں ایرانی اورترکی عورتو ںسے شادیاں کیں جو کہ خوبصورت توتھیں مگرساتھ ہی متعصب مشرکہ بھی تھیں.آخراولاد میں اس کااثر ظاہر ہوگیا.ابن مقنع.عبداللہ بن صباح اسی زمانہ میں ہوئے تھے.اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ و ہ لو گ جنہیں وہ پکارتے ہیں یعنی ان میں سے جو (خدا تعالیٰ کے)زیادہ قریب ہیں وہ (بھی)اپنے رب کا اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَ يَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ١ؕ اِنَّ (مزید)قرب چاہتے ہیں اوراس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اوراس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں تیرے عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا۰۰۵۸ رب کاعذاب یقیناایساہے جس سے خوف کیا جاتا ہے.حلّ لُغَات.الوسیلۃ:اَلْوَسِیْلَۃ وَسَلَ (یَسِلُ)کامصدر ہے اور وَسَلَ اِلَی اللہِ بِالْعَمَلِ کے معنے ہیں رَغِبَ وتقَرَّبَ متوجہ ہوااورقرب چاہا.وَسَّلَ وَتَوَسَّلَ اِلَی اللہ بِوَسِیْلۃٍ کے معنے ہیں عَمِلَ عَمَلًا تَقَرَّبَ بِہٖ اِلَیْہِ تَعَالٰی نیک عمل کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کاقرب چاہا.تَوَسَّلَ اِلَی فُلَانٍ بِکَذَا کے معنے ہیں تَقَرَّبَ اِلَیْہِ بِحُرْمَۃٍ آصِرَۃٍ تَعْطِفُہُ.کسی شخص تک ایسے مضبوط ذریعہ سے رسائی کی کوشش کی جس سے وہ مہربان ہوجائے.اَلْوَسِیْلَۃُ مَایُتَقَرَّبُ بِہٖ اِلَی الْغَیْرِِ.ذریعہ قرب.اس کی جمع وَسَائِلُ آتی ہے.(اقرب) مَحْذُوْرًا:مَحْذُوْرًا حَذَرسے اسم مفعول ہے اس کے معنے ہیں مَایُحْتَرَ زُمِنْہُ جس سے ڈرااوربچا جائے.(اقرب) تفسیر.اُولٰٓىِٕكَ کااشارہ اَلنَّبِیّٖنَ کی طرف ہے.یعنی و ہ(انبیاء)ایسے لوگ تھے جوبنی نوع انسان کو خدا کی طرف پکارتے تھے یایہ کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضورعجزوانکسار سے دعاکیاکرتے تھے.يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةََ خبر ہے اُولٰٓىِٕكَ کی.اورمطلب یہ ہے کہ انبیاء جن کی صفت ہے کہ و ہ تبلیغ میں لگے رہتے ہیں یایہ کہ دعائوں میں لگے رہتے ہیں وہ بھی باوجود اس قدر نیک اورعاشق الٰہی ہونے کے صرف اپنے
Page 377
رب کاقرب تلا ش کرتے ہیں.دوسرے کسی وجود کو معبود بناکر اس کاقرب تلاش نہیں کرتے.مقربین کے اشتیاق قرب الٰہی میں دوسروں کے لئے سبق اَیُّھُمْ اَقْرَبُ.علامہ زمخشری کاقو ل ہے اور اکثر مفسرین نے اس کی تائید کی ہے کہ اَیُّ موصولہ ہے اور اَیُّھُمْ اَقْرَبُ کے معنے مَنْ ھُمْ اَقْرَبُ کے ہیں اوریہ جملہ یَبْتَغُوْنَ کی ضمیر فاعل کا بدل ہے.یعنی یہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں.اس میں اشارہ ہے کہ جب زیادہ قرب والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے مزید قرب کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں توجن کو قرب حاصل نہیں ان کو توبہت ہی زیادہ کوشش کرنی چاہیے.خلاصہ یہ کہ خدا کاقرب ایسی چیز نہیں ہے.جودوسروں کی پرستش کے ذریعہ سے حاصل ہوسکے.اورپھر جب بڑے سے بڑانبی بھی خداکے قرب کی تلاش میں ہے اورا بھی وہ قرب الٰہی میں ترقی کی جستجوکررہاہے توو ہ تمہارے لئے زعیم اورٹھیکیدار کیسے بن سکتاہے.فرمایا جو اقرب ترین نبی ہے وہ بھی ابھی اَورقرب حاصل کرناچاہتاہے دوسرے توالگ رہے.جب نبیوں تک کی یہ بات ہے توتمہاری توہستی ہی کیا ہے.ایک اَورمعنے بھی آیت کے ہوسکتے ہیں اوروہ یہ کہ اُولٰٓىِٕكَ کااشارہ معبودین کی طرف سمجھاجائے اور یَدْعُوْن کافاعل مشرکوں کو.اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگاکہ وہ معبود جن کو مشرک بلاتے ہیں وہ تواپنے رب کے قرب کی تلاش کررہے ہیں اوراس کاخیال رکھتے ہیں کہ کون خدا تعالیٰ کازیادہ مقرب ہوتاہے.ان معنوں میں اَیُّ استفہامیہ سمجھا جائے گااوراس کاعامل فعل محذوف یامصدر محذوف سمجھا جائے گا.جیسے یَحْرُصُوْنَ اَیُّھُمْ اَقْرَبُ یایہ کہ بغیّتہم اَیُّھُمْ اَقْرَبُ.وَ اِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اَوْ اور(روئے زمین پر)کوئی ایسی بستی نہیں (ہوگی )جسے ہم قیامت کے دن سے پہلے ہلاک نہ کردیں مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا١ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ یااسے بہت سخت عذاب نہ دیں.یہ بات تقدیر (الٰہی)میں
Page 378
مَسْطُوْرًا۰۰۵۹ (پہلے سے )لکھی ہوئی ہے.حل لغات.مَسْطُوْرًا.مَسْطُوْرًاسَطَرَ سے اسم مفعول ہے.اورسَطَرَ الکَاتِبُ کے معنے ہیں.کَتَبَ.کاتب نے لکھا (اقرب) پس مَسْطُوْرٌکے معنے ہوںگے لکھی ہوئی.تفسیر.جب شرک ساری دنیا میں پھیلے گا تو عذاب بھی ساری دنیا پر آئے گا پہلے فرمایا تھا کہ اپنے معبودوںکو پکارو.و ہ تمہاری تکلیف کونہ تودورکرسکتے ہیں اورنہ اسے بٹاسکتے ہیں.اب ا س کی ایک مثال بیان فرماتا ہے اوروہ یہ کہ ایک زمانہ ایساآنے والا ہے کہ دنیا کے پردہ پر مشرک قوموں کاغلبہ ہوجائے گا اورتوحید قریباً مٹ جائے گی.اس وقت جب شرک اپنی انتہاکوپہنچ جائے گا.ہم ساری دنیا پر عذاب لائیں گے کیونکہ شرک تمام دنیا پرغالب ہوگا.اس کومٹانے کے لئے ساری دنیا کو عذاب میں مبتلاکرنا ہوگا.اس وقت ہمارے اس دعوے کی صداقت نہایت واضح ہوجائے گی کیونکہ اس پیشگوئی کے ماتحت ساری دنیا پر عذاب آئے گا.لوگ جھوٹے معبودوں کو پکاریں گے مگرکچھ نہ بنے گا.اس کی تفصیل آگے سورۃ کہف میں بیان ہوگی.اس آیت میں مسلمانوں کو بھی اس دوسرے عذاب سے ہوشیارکیا گیاہے جس سے بوجہ محمدی سلسلہ اور موسوی سلسلہ میں مشابہت تامہ پائے جانے کے انہیں خطرہ ہوسکتا تھا.وَ مَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا اورپہلے لوگوں کی تکذیب کے سواہمیں نشانات کے بھیجنے سے کسی امر نے نہیں روکا.(پس ہم نشان بھیجنے سے کس الْاَوَّلُوْنَ١ؕ وَ اٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا١ؕ طرح رک سکتے تھے ) اور(جب ) ہم نے ثمود کو (صالح کی )اونٹنی ایک روشن نشان کے طورپر دی.توانہوں نے اس وَ مَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا۰۰۶۰ پرظلم (ہی)کیا.اورہم نشانوں کو (بدانجام سے )ڈرانے کے لئے ہی بھیجا کرتے ہیں.حلّ لُغَات.ظلموابھا ظَلَمُوْابِھَا ظَلَمَ سے جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے اوراَلظُّلْمُ کے معنے ہیں.
Page 379
اَلتَّصَرُّفُ فِیْ مِلْکِ الْغَیْرِ وَمُجَاوَزَۃُ الْحَدِِّّ حد سے بڑھ جانااور دوسرے کی ملکیت پر دست درازی کرنا.انہی معنوں کے پیش نظرلفظ ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی.نیز اس کے معنے ہیں وَضْعُ الشَّیْءِ فِیْ غَیْرِ مَوْضِعِہٖ کسی بات یاکام کوبے جا اور بے محل کرنا.وَظَلَمَ الْبَعِیْرَ: ظُلْمًا اِذَانَحَرَہٗ مِنْ غَیْرِدَاءٍ.اور ظَلَمَ الْبَعِیْرَ کے معنے ہیں کہ اونٹ کو بغیر کسی بیماری کے ذبح کردیا (تاج) تفسیر.آسمانی معجزات کا سلسلہ کسی وقت بھی بند نہ ہوگا اس آیت میں یہ بتایا گیاہے کہ کسی زمانہ میں بھی آسمانی معجزات کے متعلق یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ اب ان کاسلسلہ بند ہوگیا ہے.یہ مسلمانوں کونصیحت ہے.کیونکہ مسلمانوں کے لئے بھی خطرہ تھا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوجائیں اوراس کے تازہ نشانات دیکھنے سے محرو م ہوجائیں تو یہ سمجھنے لگیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانات کاآنابند ہوگیاہے.پس انہیں ہوشیار کردیاگیا کہ ایساکبھی خیال نہ کرنا.کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نشانات دکھاتارہتاہے تاکہ اس کے بندوں کے ایمان تازہ ہوتے رہیں.دلائل اس بارہ میں کہ نشانات ہمیشہ جاری رہیں گے نشانات کے ہمیشہ جاری رکھنے کے لئے مندرجہ ذیل دلائل بیان کئے گئے ہیں.(۱)نشانات دکھانے کے خلاف صرف یہ کہاجاسکتاہے کہ ان نشانوں سے پہلوں نے کیافائدہ اٹھایا کہ آپ اٹھائیں گے.فرماتا ہے کہ اگر یہ وجہ نشان بھیجنے کے خلاف ہوتی تو پہلے نبی کے بعد پھر کوئی نشان ہی ظاہر نہ ہو تا.مگرایسا نہیں ہوا.انبیاء کے دشمن نشانات کاانکارکرتے ہی چلے گئے ہیں اورہم بھی نشانات بھیجتے چلے گئے ہیں.پس کسی وقت بھی اس وجہ سے نشانات کابھیجنا بند نہیں ہوسکتا.آدمؑ کے وقت میں بھی نشانات دکھائے گئے.نوح ؑ کے وقت میں بھی نشان دکھائے گئے.اورپھر باوجود تکذیب ثمود کی قوم کو بھی نشان دکھائے گئے جو آدم ؑ اورنوح ؑ کے بعد گذری ہے.ثمود کی مثال اس لئے دی گئی ہے کہ ثمود عرب قوموں میں سے تھے اوران کے مٹے ہوئے آثار عرب کے کفار.یہود اورنصاریٰ سب کے سامنے موجود تھے.اورتینوں قومیں ان کے حالات سے عبرت حاصل کرسکتی تھیں.عذاب سے پیشتر نشانات کا بھیجنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد دوسری دلیل یہ دی کہ جب عذاب آئے اس سے پہلے نشانات کابھیجناضروری ہوتاہے.تاکہ جولو گ عذاب سے بچائے جاسکیں بچالئے جائیں.پس جب ہم یہ خبردے رہے ہیں کہ آئندہ زمانہ میں شدید عذاب آئیں گے حتیٰ کہ دنیا کی کوئی بستی ان عذابوں سے محفوظ نہ
Page 380
رہے گی.تومسلمانوںکو سمجھ لیناچاہیے کہ اس وقت آسمانی نشانات بھی ضرو ردکھائے جائیں گے کیونکہ بغیر تخویف کے عذاب کابھیجنا ہماری سنت کے خلاف ہے.وَ اِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ١ؕ وَ مَا جَعَلْنَا اورجب ہم نے تجھے کہاتھا(کہ)تمہارارب ضرور ان لوگوںکو ہلا ک(کرنے کافیصلہ)کرچکا ہے.(تب الرُّءْيَا الَّتِيْۤ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ انہوںنے کیا فائدہ اٹھایا )اورجورؤیا ہم نے تجھے دکھائی تھی.اسے (بھی )اورا س درخت کو( بھی) جسے قرآن میں الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ١ؕ وَ نُخَوِّفُهُمْ١ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا ملعون قرار دیاگیا ہے.ہم نے لوگوں کے لئے صرف امتحان کاذریعہ بنایا تھا اور(باوجود اس کے کہ )ہم انہیں طُغْيَانًا كَبِيْرًاؒ۰۰۶۱ ڈراتے(چلے جاتے )ہیں پھر (بھی )وہ (ہماراڈرانا)انہیں ایک بہت بڑ ی سرکشی میںہی بڑھارہاہے.حلّ لُغَات.اَحَاطَ بِالنَّاسِ.اَحَاطَ بِالْاَمْرِ کے معنے ہیں اَحْدَقَ بِہٖ مِنْ جَوَانِبِہٖ کسی امر پر پورے طورپر قابوپالیا.اُحِیْطَ بِہٖ:دَنَاھَلَاکُہٗ اس کی ہلاکت قریب ہوگئی (اقرب)پس اِنَّ رَبَّکَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ کے معنے ہوں گے کہ(۱)تمہارارب ان لوگوں کو ہلاک کرچکا ہے (۲)لوگ ہررنگ میں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں.فِتْنَۃٌ.فَتَن سے مصدر ہے اوراس کے معنے ہیں.اَلْخِبْرَۃُ وَالْاِبْتِلَاءُ.آزمائش اورامتحا ن.اَلضَّلَالُ وَالْاِثْمُ وَالْکُفْرُ.گمراہی.گناہ.کفر.اَلْفَضِیْحَۃُ.رسوائی.ذلت.اَلْعَذَابُ.عذاب.اَلْمَرَضُ.مرض.الْعِبْرَۃُ.عبرت.اِخْتَلَافُ النَّاسِ فِی الْاٰرَاءِ وَمَا یَقَعُ بَیْنَہُمْ مِنَ الْقِتَالِ.اختلاف آراء اوراس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا.(اقرب) طُغْیَان.طُغْیَانٌ طَغٰی یَطْغِیْ اورطَغِیَ یَطْغٰی کامصدر ہے.اورطَغٰی کے معنے ہیں جَاوَزَ القَدْرَ وَ الحَدَّ.
Page 381
اندازہ اورحد سے بڑھ گیا.طَغٰی فُلانٌ اَسْرَفَ فِی الْمَعَاصِیْ وَالظُّلْمِ گناہوںاورظلم میں بڑھ جانا(اقرب) تفسیر.اَحَاطَ بِہٖ.کے معنے کسی چیز کااحاطہ کرلینے کے بھی ہوتے ہیں یعنی اس کے سب اجزاء کو قبضہ میں کرلیاجائے اوراس کے معنے عذاب کامل کے بھی ہوتے ہیں.کیونکہ کسی قوم کااحاطہ کرلیاجاوے تووہ بھاگ کر بچ نہیں سکتی.اس جگہ اَحَاطَ کے معنے سب کو گھیر لینے یاایک حلقہ میں لے آنے کے ہیں.فرماتا ہے کہ یاد کروجب ہم نے تم کوکہاتھا کہ ہم سب دنیا کااحاطہ کرنے والے ہیں یایہ کہ سب کوایک حلقہ میں لانے والے ہیں.آنحضرت ؐ کے سب انبیاء کو نماز پڑھانے کی تعبیر اس سے اشار ہ اسی سورۃ کی پہلی آیت کی طرف ہے جس میں اسراء والاکشف بیان کیا گیا ہے.اس کشف میں آپ کودکھایاگیاتھا کہ آپؐ نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی ہے جس کی تعبیر یہ تھی کہ سب نبیوں کی امتیں آپ کے دین میں داخل ہوںگی.آخری زمانہ کے مصائب کے بعد اسلام کی عالمگیر اشاعت سواَحَاطَ بِالنَّاسِ کہہ کر اس کشف کے مضمون کو بیان کیاگیاہے اوراس کے ذکر کاموقعہ یہ ہے کہ پہلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ سب دنیا پر عذاب آنے والا ہے اب اس کی وجہ بیان فرماتا ہے کہ اس عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کشف کو پوراکرے جو اسراء کی صورت میں تجھے دکھایا گیا تھا اور اس پیشگوئی کو پورا کرے کہ سب انبیاء کی جماعتیں اسلام میں داخل ہوجائیں گی.اس عالمگیر عذاب کے بعد تبلیغ اسلام کاراستہ کھل جائے گااورسب اقوام کو مذہب کی طرف توجہ ہوجائے گی اورمادیت سے لوگ مایوس ہوجائیںگے تب اللہ تعالیٰ اپنے فضل اوراحسان سے ان کے دل سچائی کےقبول کرنے کے لئے کھول دےگا.اوروہ محمد رسول اللہ صلعم کے جھنڈے تلے جمع ہوجائیں گے اس موعود عذاب کے آثا ر اس وقت دنیا میں ظاہرہورہے ہیں اوراس کے بعد انشاء اللہ اسلام کے پھیلنے کے سامان بہت کثرت سے پیداہوجائیں گے.آیت کے اگلے حصہ میں اس مضمون کو واضح کردیاگیا ہے.چنانچہ فرماتا ہے کہ یہ نظارہ جو ہم نے دکھایاتھا یہ لوگوں کے لئے امتحا ن کاذریعہ تھا یعنی ہم پیشگوئی توصاف لفظوں میں بھی کرسکتے تھے مگر ہم نے اس نظارہ کو تمثیلی زبان میں اس لئے بیان کیا تالوگوں کاامتحان بھی لے لیاجائے.جوابوبکری صفا ت کے تھے انہوںنے اس نظارہ کا ذکر سنااوراس پر ایما ن لے آئے اور جن کے دل تقویٰ سے خالی تھے انہوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کردیا.اللہ تعالیٰ کے نشان ایک پہلو امتحان کا بھی رکھتے ہیں اس آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشان ایک پہلوامتحان کابھی رکھتے ہیں.مگر اس کے باوجود آج مسلمان بھی ا س خیال میں مبتلا ہیں کہ پیشگوئیاں جب تک ایسے واضح الفاظ میں نہ ہوںکہ احمق سے احمق بھی ان کاانکار نہ کرے انہیںسچانہیں کہا جاسکتا.
Page 382
شجرہ ملعونہ سے کیا مراد ہے الشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ.فرمایاوہ رویا جو ہم نے تجھ کو دکھائی ہے اسے بھی ہم نے لوگوں کے لئے فتنہ یعنی آزمائش کاذریعہ بنایا ہے اوراس شجر کو بھی ہم نے لوگوں کے لئے آزمائش کاذریعہ بنایا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں آتاہے کہ وہ ملعونہ ہے.یہ شجرئہ ملعونہ کیاشے ہے ؟اس بار ہ میں مفسرین میں بہت اختلاف ہواہے.بعض کہتے ہیں اس سے مراد شجرۃ الزّقوم ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں تین جگہ آیا ہے یعنی سورئہ واقعہ.سورۃ صافّات اورسورۃ دخان میں.(کشاف،رازی و ابن کثیر زیر آیت ھذا)اوراس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب یہ بیان ہواکہ دوزخیوں کاکھانازقّوم ہے توکفار نے اس پر ہنسی اڑائی.کیونکہ یمن کی لغت میں زقّوم اس کھانے کوکہتے ہیں جومکھن اورکھجور ملا کر تیارکیا جاتا ہے.کفار نے اس لفظ کو سن کرخوب شور مچایاکہ محمدصلعم ہمیں زقوم کی خبر دیتاہے یہ تواعلیٰ درجہ کاکھاناہے.ہمیں اور کیاچاہیے.ا ن معنوں کے حق میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ شجرۃ زقوم کے متعلق بھی قرآن کریم میں آتاہے.اِنَّاجَعَلْنٰھَافِتْنَۃً لِّلظّٰلِمِیْنَ(الصافات:۶۴) ہم نے زقوم کو ظالموں کے لئے فتنہ کاموجب بنایا ہے.اوریہی الفاظ فتنہ کے شجرئہ ملعونہ کی نسبت آتے ہیں.مگرانہیں یہ مشکل پیش آئی ہے کہ قرآن میں اس کے ملعون ہونے کاکہیں ذکر نہیں.اس کا جواب انہوں نے یوں دیاہے کہ زقوم کی نسبت قرآن کریم میں آتاہے کہ وہ جہنم میں ہوگا.اورجوچیز جہنم میں ہو و ہ ملعون ہے.کیونکہ جہنم خداکے غضب کا مقام ہے.پھر اس توجیہہ پر خود ہی انہوںنے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ شجرہ کیونکر ملعون ہو سکتا ہے.ملعون تو نافرمان وجود کہلا سکتاہے اورشجرہ توبے جان چیز ہے.اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ چونکہ اس کے کھانے والے ملعون ہو گئے.اس لئے وہ شجرہ بھی ملعون کہلائے گا.بعض کے نزدیک شجرہ ملعونہ سے مراد اکاس بیل ہے بعض نے کہا ہے کہ شجرہ ملعونہ سے مراد شجرئہ کشوث ہے (روح المعانی زیر آیت ھذا).یعنی و ہ بیل جو درختوں پر چڑھتی ہے تودرخت سوکھ جاتاہے.(کشوث افتیمون کے بیجو ںکو کہتے ہیں.افتیمون ایک بیل ہوتی ہے جس کی باریک زرد شاخیں ہوتی ہیں.جس درخت کے گرد لپٹ جائے.وہ درخت خشک ہوناشروع ہو جاتا ہے.اس کی جوقسم ہندوستان میں پائی جاتی ہے اسے اکاس بیل یاامر بیل یاامر لَتَّہ کہتے ہیں.پنجاب میں غالباً اسی کانام کوڑی ویل ہے.یعنی کڑوی بیل پنجابی میں ایک دعا ہے ’’تُوکوڑی ویل دی طرح ودھیں.‘‘یعنی اکاس بیل کی طرح جو بہت جلد پھیل جاتی ہے.تیری ترقی ہو.اورجس کے تُومخالف ہو وہ تباہ ہوجائے.کیونکہ یہ بوٹی جس درخت سے لپٹ جاتی ہے اسے خشک کردیتی ہے ).
Page 383
لیکن ان معنوں کااتنا بھی ثبوت قرآن کریم سے نہیں ملتاجتناثبوت کہ شجرئہ زقوم سے ملتاہے.آنحضرت ؐ نے مروان بن الحکم کے خاندان کو بھی شجرہ ملعونہ کہا بعض روایا ت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی ہے کہ آپؐ نے مروان بن الحکم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ آپ نے تیرے باپ اورداداسے کہا کہ اِنَّکُمُ الشَّجَرَۃُ الْمَلْعُوْنَۃُ فِی الَقُرْاٰنَ.یعنی قرآن کریم میں جو شجرئہ ملعونہ کالفظ آتاہے اس سے مراد تمہاراخاندان ہے(درمنثور زیر آیت ھذا).بعض نے اس سے مراد وہ شجرئہ خبیثہ لیا ہے جس کا ذکر سورئہ ابراہیم ع۵ میںگذرچکا ہے (روح المعانی زیر آیت ھذا).میں خود بھی اس وقت تک یہی معنے کرتا رہا ہوں.کیونکہ اس کے سواباقی جس قدر معنے کئے گئے ہیں ان کاکوئی تعلق آیت قرآنی کے الفاظ سے نہیں معلوم ہوتا.میں اس کی تشریح یہ کیاکرتاہوں کہ خبیث اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیر نہ ہو.اورجس چیز میںکوئی خیر نہ ہو اس کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے کہ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً (الرعد:۱۸).یعنی جوچیز جھاگ کی طرح بے کار ہو اسے پھینک دیاجاتاہے.اورلعنت بھی دورکرنے کوکہتے ہیں.پس جس چیز کی نسبت یَذْھَبُ جُفَآءً کہا جائے.دوسرے لفظوں میں اسے ملعون بھی کہہ سکتے ہیں.مگر اس وقت کہ میں یہ نوٹ لکھنے بیٹھاہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اَورمعنے بھی سکھائے ہیں اورمیں وہ معنے بھی لکھ دیتاہوں کیونکہ ان معنوں کاآیت کے سیاق و سباق سے زیادہ گہراربط معلوم ہوتاہے.ان معنوں کو سمجھنے کے لئے پہلے شَجَرۃ کے معنے سمجھ لینے چاہئیں.شجرۃ کے معنے درخت کے بھی ہوتے ہیںاورشجرہ کے معنے خاندان یا قبیلہ کے بھی ہیں.چنانچہ لغت میں لکھا ہے شَجَرَۃُ النَّسَبِ مَایُبْتَدَأُ فِیْہَا مِنَ الْجَدِّ الْاَعْلیٰ اِلیٰ اَوْلَادِہٖ ثُمَّ اِلیٰ اَوْلَادِھِمْ وَھَلُمَّ جَرًّا(اقرب)یعنے شجرئہ نسب اسے کہتے ہیں کہ کسی جدّاعلیٰ سے لےکر اس کی اولاد اورپھراس کی اولاد اورپھران کی اولادکا ذکر کیاجائے.ان معنوں کے روسے شجرئہ ملعونہ کے معنے ایسے خاندان کے ہوسکتے ہیں جوکئی پشت تک خدائی لعنت کے ماتحت رہاہو یارہنے والاہو.ان معنوں کی سند حضرت عائشہؓ کی طرف منسوب ہونے والی اس روایت سے بھی مل جاتی ہے جو میں اوپر بیان کرآیا ہوں.یہ روایت تومیرے نزدیک غلط ہے لیکن اس سے ہم عربی کے محاورہ کی سند لے سکتے ہیں.کیونکہ بہرحال راوی اورجامع حدیث عرب ہیں اورعربی کے محاورہ کو سمجھتے ہیں.اس تشریح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیاقرآن کریم میں کسی خاندان کو ایک لمبے عرصہ تک خدائی لعنت کے نیچے آنے والا بتایاگیاہے کہ نہیں.اگرایسا ہے تووہی خاندان شجرہ ملعونہ ہے.شجرہ ملعونہ سے مراد وہ قوم ہے جس پر خدا کی لعنت ہوگی یعنی بنی اسرائیل قرآن کریم کودیکھنے سے
Page 384
معلوم ہوتاہے کہ ایک قوم اورخاندان کے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ایک لمبے عرصہ کے لئے ملعون قراردیا ہے.اوروہ حوالہ یہ ہے.لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ(المائدۃ :۷۹) بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر دائود اورعیسیٰ بن مریم نے لعنت کی ہے.اسی طرح سورۃ نساء میں یہود کا ذکر کرکے فرمایا ہے کہ اے اہل کتاب محمدرسول اللہؐ پر اس دن سے پہلے ایمان لے آئوکہ تمہاری قوم پر عذاب آجائے یاہم ان پر لعنت ڈالیں جس طرح کہ ان کے با پ دادوں پرسبت کے انکار کی وجہ سے لعنت نازل کی گئی تھی.اسی طرح یہود کی نسبت آتاہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ (المائدۃ :۱۴)یعنی یہود سے وعدہ لیاگیاتھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلعم پر جب وہ ظاہر ہوں ایمان لائیں گے لیکن انہوں نےچونکہ اس وعدہ کوپورانہیں کیا اس لئے ہم نے ان پرلعنت بھیجی ہے اسی طرح سورئہ مائدہ میں یہود کی نسبت آتاہے مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ (المائدۃ :۶۱)یعنی اے اہل کتاب تم تووہ قوم ہو.جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اورغضب نازل کیا اوربندراورسؤربنادیا.اس سے کچھ آیات آگے چل کر پھر آتاہے وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ١ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا(المائدۃ :۶۵)یعنی یہودی چندوں اورزکوٰۃ وغیرہ کے مسائل پر تمسخرکرکے کہتے ہیں.خداان کومال نہیں دیتا اس کے ہاتھ بند ہوگئے ہیں ان کے اس گستاخانہ کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کردیاہے کہ اس قوم میں بخل پیداہوجائےگا اورمال کی محبت بڑھ جائےگی اوران پر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑتی رہے گی.اس کے علاوہ اورمتعدد مقامات پر یہود کے ملعون ہونے کا ذکر آتاہے پس بنی اسرائیل جوایک نسل کے لوگ تھے ان پر متواترلعنت پڑی اورقرآن کریم نے بھی ان کی قوم پرلعنت ڈالی اورفرمایاکہ اس قو م کو صرف دوطرح امن ملے گا یاتویہ دوسری زبردست قوموں کی پناہ میں چلی جائے یا پھر مسلمان ہوجائے.ان دونوں طریقوں کے سواان کو کبھی امن نہ ملے گا.پس میرے نزدیک آیت زیربحث میں شجرئہ ملعونہ سے مراد بنی اسرائیل کی قو م ہے.اور چونکہ یہ سورۃ بھی خصوصاً سورۃ بنی اسرائیل کے متعلق ہے.حتٰی کہ اس کاایک نام رسول کریم صلعم نے سور ئہ بنی اسرائیل بتایاہے(ابن ماجہ کتاب اقامۃ الصلٰوۃ باب عدد سجود القرآن) اور چونکہ اس آیت میں بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے کیونکہ ا س آیت میں اسراء کا ذکر کیاگیا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بنی اسرائیل کے مرکز میں دیکھا اوروہاں نماز پڑھائی.پس اسراء والی رؤیاکا ذکرکرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ رؤیا بھی لوگوں کے امتحان کاذریعہ ہے.اوربنی اسرائیل جن کااس رویا میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے وہ بھی ایک امتحان ہیں یعنی وہ ہمیشہ اسلام کی بلاوجہ مخالفت کرتے رہیں گے.چنانچہ دیکھ لوکہ یہود کوسب سے زیادہ امن اسلامی ممالک میں ملتاہے اورپھر بھی یہ لوگ اسلام سے دشمنی ہی کرتے چلے جاتے ہیں اورنہیں سمجھتے کہ ان کے امن
Page 385
کاواحد ذریعہ اسلام ہے یہودی رہ کر وہ دنیاکے ظلموں کاتختہ مشق ہی بنے رہیں گے.آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم تو اس قوم کو ان کاانجام بتابتاکر ڈراتے ہیں لیکن یہ سرکشی میں اورزیادہ بڑھتی جاتی ہے.اس آیت کا تعلق پہلی آیت سے ہے ا س آیت کاتعلق پہلی آیا ت سے یہ ہے کہ ان میں آخری زمانہ کے خطرناک عذاب کو بطور مثا ل پیش کیاگیاتھا.اب اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ عذا ب اسراء والے کشف کا طبعی نتیجہ ہے کیونکہ اس عذاب سے اسلام کی ترقی وابستہ ہے اوراس کے بعداسلام کی وسیع اورعالمگیر اشاعت مقدر ہے.موجودہ اور سابقہ جنگ یہود کی دخل اندازی سے ہوئی اورساتھ ہی یہود کا ذکر کرکے یہ بتایاکہ یہ قوم بھی فتنہ ہے یعنی وہ دوسرافتنہ اس فتنہ گرقوم کے ذریعہ سے پیدا ہوگاچنانچہ دیکھ لوکہ گزشتہ جنگ عظیم بھی یہود کی دخل اندازی کی وجہ سے ہوئی تھی اورموجودہ جنگ بھی انہی کی وجہ سے ہے.پہلی جنگ میں یہود نے منظم طورپر جرمنی قوم کے خلاف کام کیا.جس کانتیجہ یہ ہواکہ اب جرمنوں نے یہود پر ظلم کرنا شروع کیا اوربدلہ لیا.انہوں نے پھر ان کے خلاف پروپیگنڈا کیااورموجود ہ جنگ شروع ہوئی.روس کے انقلاب میں بھی کہ وہ اس عذاب کاایک حصہ ہے یہود کاسب سے بڑادخل ہے اورروس کے کئی بڑے بڑے لیڈر یہود ی النسل ہیں.پہلی جنگ عظیم سے پہلے بعض اخبارات نے یہود کی بعض تحریرات شائع کی تھیں کہ یہود سازش کررہے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کراکے فلسطین واپس جانے کے سامان پیداکریں.آئندہ واقعات نے اس کی تصدیق کردی.مگرجیسا کہ قرآن کریم نے بتایا ہے یہود کافلسطین میں آناعارضی ہوگا ان کویہ ملک دائمی طورپر نہیں مل سکتا کیونکہ دائمی طورپرتویہ مسلمانوں کے لئے مقدرہوچکا ہے.وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ١ؕ اور(اس وقت کو بھی یاد کرو)جب ہم نے فرشتوں کو کہا تھا (کہ)تم آدم کے ساتھ(ساتھ)سجدہ کروتوانہوں نے قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًاۚ۰۰۶۲ (توا س حکم کے مطابق )سجدہ کیا.مگرابلیس (نے نہ کیا ).اس نے کہا(کہ)کیا میں اس کے ساتھ سجدہ کروں جسے تونے کیچڑ سے پیدا کیا ہے حلّ لُغَات.لِاٰدَمَ.ل جارہ کے بائیس معنے ہیں.ان میں سے ایک معنے مَعَ کے ہیں چنانچہ ایک
Page 386
شاعرکاشعرہے ؎ فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا کَاَنِّیْ و مَالِکَا لِطُوْلِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَیْلَۃً مَعَا یہاں لِطُوْلِ میں ل کے معنے مَعَ کے کئے گئے ہیں(مغنی اللبیب حرف ا لام )پس وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ کے معنے ہوں گے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کے ساتھ سجدہ کرو.اِبْلِیْسَ.ابلیس کے معنی کے لئے دیکھو حجر آیت نمبر ۳۲.اَبْلَسَ مِنْ رَحمۃِ اللہِ کے معنے ہیں.یَئِسَ.ناامید ہوگیا.اوراَبْلَسَ فِی أَمْرِہِ کے معنی ہیں.تَحَیَّرَ.حیران ہوگیا.وَقِیْلَ اِبْلِیْسُ مِنْ اَبْلَسَ بمَعْنَی یَئِسَ وَتَحَیَّرَ.یعنی اَبْلَسَ کے معنی ناامید اور حیران ہونے کے ہیں.اور اِبْلِیْسُ اسی سے بناہے.یعنی ناامید اورحیران.اس نام سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہوگیا ہے.اورحیران رہ گیا ہے.جَمْعُہُ اَبَالِیْسُ وَ اَبَالِسَۃٌ.اس کی جمع اَبَالِیْسُ اوراَبَالِسَۃٌ آتی ہے.(اقرب) اَلطِّیْنُ :اَلطِّیْنُ تُرَابٌ اَوْ رَمْلٌ وَکِلْسٌ یُجْبَلُ بِالْمَاءِ وَیُطْلٰی بِہٖ.مٹی یاریت اورچونہ جس میں پانی ملایا گیاہو.اوراس کے ساتھ لپائی کی جائے (اقرب) تفسیر.چونکہ پہلی آیات میں یہود کی سرکشیوں کا ذکر کیا تھا.اب اس پر روشنی ڈالنے کے لئے آدم کے واقعہ کو بطورتمثیل پیش کیا ہے کہ انبیاء کی مخالفت ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے.ابوالبشر آدم جوسب سے پہلے نبی تھا.اس کی بھی ایک ابلیس نے مخالفت کی اورکہاکہ یہ ادنیٰ ہے.میں اس سے اچھا ہوں.پھر اس کی اطاعت کیونکر کروں.یہی ابتلاء یہود کے سامنے ہے.و ہ بھی اپنے آپ کو محمدؐرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوران کی قوم سے افضل سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ خیا ل راسخ ہے کہ بنواسحاق سب ابراہیمی برکات کے وارث ہیں.اوربنواسماعیل گویا محروم الارث کئے ہوئے ہیں.پس یہ تکبر ان کے راستہ میں روک بننے والا ہے.
Page 387
قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِيْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ١ٞ لَىِٕنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى (اورنیز)اس نے کہا (کہ توہی مجھے)بتا(کہ کیا ) یہ (میرامطاع ہوسکتا)ہے جسے تونے مجھ پرشرف دےدیاہے.يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلًا۰۰۶۳ اگر تونے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو(مجھے تیری ہی ذات کی قسم ہے کہ )میں اس کی (تمام)اولاد کو قابو میں کر لوںگاسوائے تھوڑے سے لوگوں کے (جنہیں توبچالے ).حلّ لُغَات.کَرَّمْتَ عَلَیَّ کَرَّمَہُ(تَکْرِیْمًا وَتَکْرِمَۃً)کے معنے ہیں عَظَّمَہُ وَنَزَّھَہُ اس کو اعزازو شرف دیااوراس کو پاک ٹھیرایا (اقرب)پس ھٰذالَّذِیْ کَرَّمْتَ عَلَیََّّ کے معنے ہوںگے کہ (کیا )یہ (میرامطاع ہوسکتا) ہے جسے تونے مجھ پر شرف دےدیا.لَاَحْتَنِکَنَّ لَاَحْتَنِکَنَّ اِحْتَنَکَ سے مضارع واحد متکلم کاصیغہ ہے اوراِحْتَنَکَ الْفَرْسَ کے معنے ہیں جَعَلَ الرَّسَنَ فِی فِیْہِ.گھوڑے کے منہ میں لگام دیا.اوراس کوقابو میں کرلیا.اِحْتَنَکُہُ: اِسْتَوْلیٰ عَلَیْہِ.اس پر غالب آگیا.اس پر قابو پالیا.اِحْتَنَکَ زَیْدًا:اَخَذَمَالَہُ کُلَّہٗ.زید کا سارا مال لے لیا.اِحْتَنَکَ الْـجَرَادُالْاَرْضَ کے معنے ہیں اَکَلَ مَاعَلَیْھَا وَاَتَی عَلیٰ نَبَاتِھَا.ٹڈیوں نے زمین کی سب چیزوں کوختم کردیا (اقرب)پس لَاَحْتَنِکَنَّ کے معنے ہوں گے کہ میں ضرور ان پر قابو پالوں گا.تفسیر.یعنی شیطان نے زبان حال سے مطالبہ کیا کہ مجھے اس وقت تک موقعہ مل جائے جوان کی ترقی کے لئے مقدر ہے.تومیں ان کے منہ میں لگام دےکر جدھر چاہو ں گالئے پھروں گا ۱؎.اس آیت میں قیامت سے مراد مومنوں کی ترقی کا وقت ہے کیونکہ ا س وقت کافروں کی قیامت بذریعہ تباہی کے.اورمومنوں کی قیامت بذریعہ کامیابی کے آجاتی ہے.اِلَّا قَلِيْلًا کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ تھوڑے سے آدمی میرے تصرف سے بچیں گے.اوریہ بھی کہ ان کے اعمال اکثر میری فرمانبرداری میں ہوں گے.تھوڑے اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں گے.
Page 388
بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک دعویٰ کیا اوراسے پوراکردکھایا.اس نے کہاتھا لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗۤ چنانچہ دنیا میں بد ی بہت ہے اورنیکی کم.اس کے مقابل خدا تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیامگراس کو پورانہ کرسکا.اس نے فرمایا تھا.مَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّالِیَعْبُدُوْنِ.مگر اکثر انسان خدا کے بندے نہیں شیطان کے بندے ہیں.یہ اعتراض قلت تدبّرکانتیجہ ہے.کیونکہ حقیقتاً بدی نیکی کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے.بڑے سے بڑے جھوٹ بولنے والے کوہی لے لو.اس کی ساری عمر کے کلام کوجمع کرو توضرو را س کے سچ زیادہ ہوں گے اورجھوٹ بہت تھوڑے.یہی حال دوسری بدیوں کاہے.دنیا میں اکثر انسان نیک نیت ہیں اوراپنی طرف سے نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں.گوبعض حالات میں جذبات سے دب بھی جاتے ہیں.پس یہ غلط ہے کہ شیطان کامیاب ہوگیا.میں تو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی بدی کازیادہ مشہورہوجانا یہ بھی شیطان کی ناکامی کاثبوت ہے.کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت نیک ہے اوروہ تھوڑے سے گناہ کی بھی برداشت نہیں کرسکتی.قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ (اللہ تعالیٰ نے )فرمایا چل(دورہو )کیونکہ (تیری اور)ان میں سے جوبھی تیری پیروی کر یں توجہنم یقیناًتمہاری جَزَآءً مَّوْفُوْرًا۰۰۶۴ (اوران کی )سب کی جزاہے (یہ)پوراپورابدلہ (ہے).حلّ لُغَات.موفورًا.مَوْفُوْرًاوَفَرَ(یَفِرُ)سے اسم مفعول ہے اوراس کے معنے ہیں اَلشَّیْءُ التَّامُ.مکمل چیز جَزَاءٌ مَوْفُوْرٌ.لَمْ یُنْقَصْ مِنْہُ شَیْءٌ.پوراپورابدلہ (اقرب) تفسیر.شیْءٌ موفورٌ پوری چیز اوروہ چیز جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو.یعنی ہرایک کے لئے اس مقام میں جزاء تام ہوگی.یہ مراد نہیں کہ سزاکم نہ ہوگی.بلکہ مراد یہ ہے کہ سزاایسی چیز ہے کہ انسا ن اس کی نسبت یہ نہیں کہہ سکتاکہ مجھے اورچاہیے.پس ہرشخص جہنم میں اپنی سزامیں مشغول ہوگا اورطرف توجہ نہ ہوسکے گی ورنہ جیساکہ قرآن کریم سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ سزاکے معاملہ میں ہمیشہ عفواوررحمت کو مدنظر رکھتاہے.اس آیت سے معلو م ہوتاہے کہ سزاقلبی ہوگی اورہرایک اپنے اپنے قلب کی کیفیت کے مطابق سزاپائے گا.
Page 389
جیسے درخت زمین سے اپنی حالت کے مطابق غذاحاصل کرلیتا ہے.ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دوانسانوں کے دل بھی پوری طرح مشابہ نہیں.حالانکہ کروڑہاانسان پیداہوئے اورہوں گے مگرہرایک کے دل کی کیفیت وحالت الگ الگ ہے اسی طرح ہر اک کی سزابھی الگ الگ ہونی ضروری ہے.اوریہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ سزاقلبی ہو اورہراک اپنے اعمال کے طبعی نتائج کو بھگتے.وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ اور(ہم نے کہا جا)ان میں سے جس پر تیرابس چلے.اسے اپنی آواز سے فریب دے کر (اپنی طرف ) بلا.اوراپنے بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ سواروں اورپیادوں کو ان پر چڑھالا.اور(ان کے)مالوں اوراولادوں میں ان کا حصہ دار بن.اوران سے( جھوٹے) وَعِدْهُمْ١ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا۰۰۶۵ وعدے کر(اورپھر اپنی کوششوں کانتیجہ دیکھ)اورشیطان جو وعدے بھی کرتا ہے فریب کی نیت سے ہی کرتا ہے.حلّ لُغَات.اِسْتَفْززْ.اِسْتَفْزِزْ اِسْتَفَزَّسے امرکاصیغہ ہے.اوراِسْتَفَزَّہُ(الخَوْفُ)کے معنے ہیں.اِسْتَخَفَّہُ خوف نے اسے حواس باختہ کردیا.اِسْتَدْعَاہُ.اسے بلند آواز سے بلایا.اَخْرَجَہُ مِنْ دَارِہِ.اس کو گھرسے نکال دیا.اَ زْعَـجَہُ.اسے بنیادسے اکھیڑ دیا وَیُقَالُ خَتَلَہٗ حَتّٰی اَلْقَاہُ فِی مَھْلَکَۃٍ.بعض کہتے ہیں کہ اِسْتَفَزَّ کے معنے کسی کودھوکادے کرہلاکت میں ڈالنے کے ہیں.قَتَلَہُ.نیز اس کے معنے ہیں اس کوقتل کردیا (اقرب) وَاَجْلِبْ عَلَیْھِمْ.وَاَجْلِبْ عَلَیْھِمْ اَجْلَبَ سے امرکاصیغہ ہے اوراَجْلَبَ الْقَوْمُ کے معنے ہیں اِخْتَلَطَتْ اَصْوَاتُھُمْ وَضَـجُّوا.لوگوں کی آوازیں مختلط ہوگئیںاورانہوں نے شوربرپاکیا.تَـجَمَّعُوْامِنْ کُلِّ وَجْہٍ لِلْحَرْب.ہرطرف سے لڑائی کے لئے جمع ہوگئے.وَفِی الْقُرْاٰن وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ اَیْ صِحْ اورقرآ ن مجید کی آیت وَاَجْلِبْ عَلَیْھِمْ میں اَجْلِبْ کے معنے آواز بلند کرنے کے ہیں.(اقرب) الخیل.اَلْخَیْلُ جَمَاعَۃُ الْاَفْرَاسِ.گھوڑوں کی جماعت.اس کامفرد نہیں آتا.وَالْفُرْسَانُ عَلَی الْمَجَازِ اَیْ رِکَابُ الْخَیْلِ اورخیل بول کرسوارمرادلینے مجازی معنے ہیں وَمِنْہُ فِی الْقُرْاٰنِ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ
Page 390
اِیْ بِفُرْسَانِکَ وَمُشَاتِکَ اورآیت وَ اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ میں خیل سے مراد سوار اور رَجِل سے مراد پیدل چلنے والے کے ہیں (اقرب) رَجِلٌ رَاجِلٌ کی جمع ہے اور رَاجِلٌ اس شخص کے لئے بولتے ہیں جس کے پاس سواری نہ ہو.(اقرب) تفسیر.اسلام کے نزدیک فطرت میں نیکی ہے اِسْتَفْزِزْ کے معنے ہیں اپنی جگہ سے ہٹالے.اس سے معلو م ہواکہ انسان پہلے نیکی کے مقام پر کھڑاہوتاہے پھراگر اس پر شیطان کااثر ہوجائے.تواپنے اصل مقام کو چھو ڑکر بدی کی طرف چلاجاتاہے.اس بارہ میں عیسائی تعلیم اوراسلام کی تعلیم میں کتنا بڑافرق ہے.عیسائیت توکہتی ہے کہ انسان کی فطرت میں بدی اصل ہے.اورکفارہ کے ذریعہ اسے بدی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لایا گیا ہے(دنیا کا منجی از ماسٹر برکت اے خان صفحہ ۲۰،۲۱).مگر اسلام کہتاہے کہ اصل مقام نیکی ہے.مگرشیطان اس سے ہٹاکر لے جاتاہے.بِصَوْتِكَمیں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض طبائع ا س قدرکمزورہوتی ہیں کہ وہ صرف دھمکیاں سن کرہی ڈرجاتی ہیں یااعتراض سن کرہی شک میں پڑ جاتی ہیں.ان میں مقابلہ کی جرأت نہیں ہوتی اورنہ تحقیق کی ہمت.اس آیت میں شیطانی حملو ںکی اقسام بیان فرمائی ہیں.بعض کو وہ دھمکا کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتاہے.یعنی شیطانی لوگ غرباء اوربیکس لوگوں کو ڈراڈراکر نبیوں کے ساتھ شامل ہونے سے روکتے ہیں.بعض کوسواروں اورپیادو ںکے ذریعے سے نیکی سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے.یعنی انہیں قسم قسم کے دکھ دیئے جاتے ہیں.اوربعض کوبدرسوم اور صحبت کے ذریعہ سے تباہ کیا جاتا ہے.اوربعض کومال اوردولت کی لالچ دے کر حق کے ماننے سے روکاجاتاہے.مگر جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ ان باتوں سے قابو میں نہیں آتے ،وہی لو گ متاثرہوتے ہیں جن کے دل میں مرض ہوتی ہے.یہ جو فرمایا ہے شَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ اس کایہ مطلب ہے کہ شیطانی لوگ انبیاء کے خلاف جتھے بھی بناتے ہیں اور اپنے مالوں اوراولاد کوجمع کرکے متفقہ طور پر نبیوں پر حملہ کرتے ہیں گویا اپنی سب طاقتوں کو جمع کرلیتے ہیں.آئمہ کفر کی انبیاء کے خلاف چالوں کی اقسام ان اقسا م پر اگر غورکیاجائے تومعلوم ہوتا ہے کہ آئمہ کفار تین قسم کی چالیں انبیاء کے خلاف چلتے ہیں.جولوگ کمزور ہوں.ان کے لئے ڈرانے اورتکلیف دینے کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں.جوبرابر والے ہوں ان سے جتھہ بازی کے اصول پر اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں.اورجو طاقتور ہوں انہیں غنائم کے وعدے دے کر یالیڈری کی امیدیں دلاکر پھنساتے ہیں.نبیوں کے مقابلہ پر ان تینوں
Page 391
گروہوںکو ان تینوں طریق سے پھنسانے کی مثالیں اس قدر کثر ت اورتواترسے ملتی ہیں کہ اس کے متعلق مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں.اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ١ؕ وَ كَفٰى بِرَبِّكَ جو میرے بندے ہیں ان پر تیراہرگز کچھ تسلط نہیں (ہوسکتا)اور(اے میرے بندے )تیرارب کارساز ہوکر وَكِيْلًا۰۰۶۶ (تیرے لئے )کافی ہے.تفسیر.اس آیت میں بتایاگیا ہے جو اللہ تعالیٰ کابندہ بن جائے.اس پر شیطان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا.کیونکہ شیطان کو صرف یوم قیامت تک کی مہلت حاصل ہوتی ہے.یعنی جب تک انسان روحانیت میں کمزور ہو شیطان کے حملہ سے دیتا ہے.جب اس میں روحانی طاقت پیداہوجائے اس میں دلیری آجاتی ہے اوروہ دھمکیوں ، تکلیفوں اورلالچوں سے نہیں ڈرتا.شیطانی حملوںسے بچنے کا گر دوسرے اس آیت میں شیطانی حملوں سے بچنے کاگر بھی بتایاگیاہے اوروہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کاعبد بن جائے.یعنی اپنے آپ کو اس کے سپرد کردے اوراپنی طاقتوں کی بجائے اس پر توکل کرے.جس کا خدا تعالیٰ وکیل ہوجائے شیطان اس کاکچھ نہیں بگاڑ سکتا.رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ (اوراے میرے بندو)تمہارارب وہ (کریم ذات)ہے.جوتمہارے لئے کشتیوں کوسمندر میں چلاتاہے تاکہ فَضْلِهٖ١ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا۰۰۶۷ تم اس کے فضل کو ڈھونڈو.وہ یقیناً تم پر بار با ررحم کرنے والا ہے.حل لغات.یُزْجِیْ.یُزْجِیْ اَ زْجٰی سے مضارع واحد مذکرغائب کاصیغہ ہے اوراَ زْجَاہ (اِزْجَاءً )کے معنی ہیں زَجَّاہُ یعنی ا س کوچلایا اورآہستگی سے آگے کیا.وَمِنْہُ فِی الْقُرْآنِ رَبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِیْ لَکُمْ الْفُلْکَ.اَیْ
Page 392
یُجْرِیْہِ وَیَسُوْقُہُ اورآیت یُزْجِی الْفُلْکَ الخ میں یُزْجِیْ کے معنے چلانے کے ہیں (اقرب)پس رَبُّکُمُ الَّذِی یُزْجِیْ لَکُمْ الْفُلْکَ فِی الْبَحْرِ کے معنے ہوئے.تمہارارب وہ ہے جو تمہارے لئے کشتیوں کو سمندر میں چلا تا ہے.تفسیر.اس میں بتایا ہے کہ حقیقی انعامات تو اللہ تعالیٰ نے پیداکئے ہیں.مگرلوگ ان کی قدر نہیں کرتے.خشکی پر تو سامان ہیں ہی سمندر میں کشتیاں بناکر اس نے باہمی تعلقات کو وسیع کردیا ہے.ورنہ جزائرمیں بسنے والے لوگ براعظموں کے لوگوں سے اوربراعظموں کے لو گ جزائر والوں سے غافل رہتے.اسلام عالمگیر مذہب ہے میرے نزدیک یہ مثال اس جگہ اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے دی ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اورسب دنیامیں پھیلے گا اوریہ امر چونکہ جہازوں کے ساتھ وابستہ ہے جن کے بغیر سمندروں کاسفر طے نہیں کیا جاسکتا.سمندر کی مثال دے کر مسلمانوں کو جہاز رانی کی طرف توجہ دلائی اس لئے اس جگہ خصوصاً سمندر اورجہازوں کی نعمت کا ذکر فرمایا کہ یہ نعمت مسلمانوں کوخاص طور پر ملنے والی ہے.چنانچہ مسلمان گوآجکل جہاز رانی میں کمزورہیں.لیکن ایک زمانہ ایساتھا کہ سب دنیا میں مسلمانوں کے جہاز چلتے تھے ،بحری نقشے اورراستے سب مسلمانوں کے تیار کئے ہوئے ہیں.ہندوستا ن کی طرف یورپ کے لوگوں کابحری سفر بھی ایک عرب مسلما ن کا ممنون احسان ہے.جو بھٹکتے ہوئے پُرتگیزی جہازوں کو افریقہ کے اوپر سے لاکر ہندوستان تک پہنچا گیا.(Arabian Students vol.1 p:86 to 93) وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اورجب سمندر میں (طغیانی پیدا ہونے کی وجہ سے )تمہیں تکلیف پہنچے.توا س کے سوا(دوسرے وجود )جن کوتم اِيَّاهُ١ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ١ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ پکارتے ہو(تمہارے ذہنوں سے )غائب ہوجاتے ہیں.پھر جب وہ تمہیں بچاکر خشکی پرلاتاہے.توتم (اس کی كَفُوْرًا۰۰۶۸ طرف سے )اعراض کرلیتے ہو.اورانسان بہت ہی ناشکر گذار ہے.تفسیر.وَ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ.الآیہ.اوراگر سمندر میں کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے توسارے معبودان باطلہ
Page 393
تمہیں بھو ل جاتے ہیں.صرف اس وقت خدا تعالیٰ ہی یا د آتاہے مگر جب تم کو نجا ت دےکر خشکی پر پہنچاتاہے.توپھر اعراض کرنے لگ جاتے ہو.یعنی انسان بڑاہی ناشکراہے.ہمیشہ اپنی حالت کو بھول جاتا ہے.جب مصیبت میں ہوتاہے توکہتاہے کہ اگر اس سے نجات پاجائوں گا توضرور نیکی کروں گا.مگر جب وہ تکلیف کی حالت گذر جاتی ہے تو پھر سب قول و قرار بھو ل جاتاہے.اس آیت میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے کہ کفار کے طریق کو اختیار نہ کرنا اورترقی کے زمانہ میں بھی خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا تامصیبت کے وقت و ہ تمہاری مدد کاخیا ل رکھے.اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ توکیا تم اس بات سے بے خوف (اورمحفو ظ)ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارہ پر( ہی زمین میں )دھنسادے یاتم پر عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًاۙ۰۰۶۹ سنگریزے نازل کرے.(اور)پھر تم اپناکوئی کارساز (اورچارہ گر )نہ پائو.حل لغات.یَخسف :یَخْسِفُ خَسَفَ سے مضارع ہے اوراس کے لئے دیکھو نحل ۴۶.حاصبًا حَاصِبًاحَصَبَ سے اسم فاعل ہے اورحَصَبَہٗ (یَحْصِبُ) کے معنے ہیں رَمَاہُ بِالْحَصْبَاءِ.اس کوکنکر مارا.حَاصِبٌ کے معنے ہیں رِیْـحٌ شَدِیْدَۃٌ تَحْمِلُ التُّرَابَ وَالْحَصْبَاءَ.سخت ہواجو مٹی اورکنکر اٹھاکرپھینکے وَقِیْلَ ھُوَ مَاتَنَاثَرَ مِنْ دُقَاقِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.بعض کہتے ہیں.وہ اولے جو ہواکے ساتھ گرتے ہیں.السَّحَابُ لِاَنَّہُ یَرْمِیْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.باد ل کیونکہ وہ بھی اولے برساتے ہیں (اقرب) تفسیر.فرماتا ہے خشکی میں دلیر ہوتے ہومگر کیاخدا تعالیٰ تم پر خشکی میں عذاب نہیں بھیج سکتا.کیا وہ تم کو زمین میں غائب نہیں کرسکتا.یاپتھروں کامینہ تم پر نہیں برساسکتا.پھر سمندر اورخشکی میں فر ق کرنے سے تم کیافائد ہ حاصل کرسکتے ہو.جنگ بدر کی پیشگوئی میرے نزدیک اس آیت میں جنگ بدر کی پیشگوئی ہے.جنگ بدر کے موقعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں کنکر پکڑ کرپھینکے تھے.اسی وقت ایک تیز ہواچل پڑی جس کے ساتھ کنکر اڑ اڑ کر کفار کی آنکھو ں میں پڑنے لگے.نیز چونکہ کفار کے سامنے کی طرف سے ہواآتی تھی کفارکے تیروں کازوراس ہواکی وجہ سے کم ہوجاتاتھا.اورمسلمانوں کے تیروں کازور بوجہ باد موافق کے بڑھ جاتاتھا (دلائل النبوۃ للبہیقی
Page 394
باب التقی الجمعن...).عرب کے بسنے والے کیا مسلمان، کیایہودی ،کیامسیحی سمندر سے سخت ڈرتے تھے.اس لئے سمندر کی مثال سے انہیں سمجھایا ہے کہ سمندر میں جاتے ہو توذراسے طوفان سے گھبراجاتے ہو کہ شائد بداعمالیوں کی وجہ سے عذاب آنے لگاہے لیکن خشکی پر دلیر ہوتے ہو.مگریاد رکھو ہم تم کو خشکی میں تباہ کردیں گے.اس جگہ مسلمانوں کو سمندری سفروں کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ جب خشکی تری دونوں میں خطرات ہیں توتم اس حماقت میں مبتلانہ ہونا کہ خشکی پر بیٹھے رہو اورسمندر کے سفرکونظرانداز کردو.اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ یاتم اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں (پھر )دوسری بار اس (یعنی سمندر)میں لوٹالائے.اور تم پر ایک تُند عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ١ۙ ثُمَّ ہواچھوڑ دے اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کردے.(اور)پھر اس (عذاب)پرتم ہمارے خلاف لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا۰۰۷۰ اپنا کوئی مددگار نہ پائو.حلّ لُغَات.قاصفًا:قَاصِفًا قَصَفَ(یَقْصِفُ)سے اسم فاعل ہے.اورقَصَفَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں.کَسَرَ ہُ فَانْکَسَرَ کسی چیز کو توڑاتووہ ٹوٹ گئی.قَصَفَ الرَّعْدُ:اشْتَدَّ صَوْتُہ بجلی کی کڑ ک کی آوا ز سخت ہوگئی اور رَعْدٌ قَاصِفٌ کے معنے ہیں اَیْ صَیِّتٌ.خوب گرجنے والی بجلی.رِیْحٌ قَاصِفٌ اَیْ شَدِیْدَۃٌ تَکْسِرُ مَامَرَّتْ بِہٖ مِنَ الشَّجَرِ وَغَیْرِ ہِ اور رِیْحٌ قَاصِفٌ اس ہواکو کہیں گے کہ جس درخت یا اور کسی چیز پر وہ گزرے تو اس کو توڑ دے.(اقرب) تَبِیْعًا:تَبِیْعًا التَّبِیْعُ کے معنے ہیں النَّاصِرُ.مددگار.التَّابِعُ.تابع(اقرب) تفسیر.فتح مکہ کی پیشگوئی اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى.اس میں میرے نزدیک فتح مکہ کے وقت کی خبر دی ہے اس وقت بہت سے کفار مکہ چھو ڑ کربھاگ گئے تھے.اورکشتیوں میں سوار ہوکر یمن یاحبشہ کی طرف روانہ ہوگئے تھے.مگرسمند رمیں طوفان آگیا.اوربہت سے غرق ہوگئے.عکرمہ بن ابی جہل بھی بھاگنے والوں میں
Page 395
سے تھے.مگران کوجہاز نہ ملا اورپیچھے رہ گئے.اتنے میں ان کی بیوی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لئے معافی حاصل کرلی.اورساحل پر جاکر واپس لے آئی(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام ذکر الاسباب الموجبۃ المسیر الی مکۃ...اسلام عکرمۃ و صفوان).وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ اورہم نے بنی آدم کو (بہت )شرف بخشاہے.اوران(کو اوران کے سامانوں )کو خشکی اورتری میں اٹھایا ہے رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ اورانہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیاہے.اورجن (اقسا م کی مخلوقات)کوہم نے پیدا کیاہے.ان میں سے خَلَقْنَا تَفْضِيْلًاؒ۰۰۷۱ بہتوں پر ہم نے انہیں بڑی فضیلت دی ہے.تفسیر.قوموں کو ایک دوسرے پر تفاخر نہیں کرنا چاہیے اس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کوعزت بخشی ہے.نہ کہ خاص اقوام کو پس قوموں کو ایک دوسرے پر تفاخر نہیں کرناچاہیے.اس سے یہود اورقریش کو نصیحت کی ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے معزز سمجھتے تھے.اوربتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اک قوم کو عزت دی ہے.مگربعض اقوام اس عزت سے فائد ہ نہیں اٹھاتیں اورخدا تعالیٰ کے کھو لے ہو ئے راستوں کو اپنے لئے بندکرلیتی ہیں.سمندر اور خشکی یکساں طور پر انسانی ترقی کے لئے مقدرہے وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے.کہ سمندر اورخشکی کویکساںطور پر اللہ تعالیٰ نے انسانی ترقی کے لئے مقررکیا ہے.پس اگر کوئی قوم عزت حاصل کرناچاہے تواسے یکساں طورپردونوں سے فائدہ اٹھاناچاہیے.لوگ کہتے ہیںکہ قرآن کریم محمد(صلی اللہ علیہ وسلم)کابنایاہواہے(ستیارتھ پرکاش باب ۱۴ دین اسلام ).کیایہ باتیں جو اس جگہ بیا ن ہوئی ہیں.ایک عرب کے رہنے والے کے منہ سے نکل سکتی ہیں.خصوصاً اس کے منہ سے جس نے کبھی کشتی میں سفر تک نہیں کیا.
Page 396
افسوس کہ مسلمانوں نے چندگذشتہ صدیو ںسے اس نصیحت کو بھلادیا.اوران کی طاقت کمزورہوگئی.اگر وہ سمندری بیڑوں کاخیال رکھتے تواسلام کبھی اس قدرکمزور نہ ہوتاجس قد ر کہ اب ہے.فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان بعض قسم کی مخلوق سے افضل ہے.سب قسم کی مخلوق سے نہیں (تفسیر البغوی زیر آیت ھذا).مگر یہ استدلال غلط ہے کیونکہ اس جگہ بنی آدم کا ذکر بہ حیثیت جماعت ہے.اوراس میں کیا شک ہے کہ سب انسان توسب مخلوق سے افضل نہیں ہیں.انسانوں میں بعض تونہایت گند ے ہیں اورجانوروں سے بھی بدتر ہیں.بعض معمولی بھلے مانس ہیں.اورجانوروں سے اچھے ہیں.بعض بہت اچھے ہیں.اورعام فرشتوں سے بھی اچھے ہیں.بعض اعلیٰ مقام پر ہیں اوراعلیٰ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں.غرض انسان سب مخلوق سے افضل نہیں.بلکہ بعض انسان سب مخلوق سے اچھے ہیں.اورانسان بحیثیت انسان کے اکثر مخلوق سے اچھاہے.کیونکہ سورج،چاند ،ستارے ،گھوڑے ،بیل،اونٹ ،بکریاں یہ کافرو مومن سب ہی کے کام کررہی ہیں اورسب ہی کی خدمت پر لگائی گئی ہیں.پس انسان بلحاظ جنس کے اکثر مخلوق سے افضل ہے.اورانسان بلحاظ کامل فرد کے سب مخلوق سے افضل ہے.يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍۭ بِاِمَامِهِمْ١ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ اور(اس دن کو بھی یاد کرو)جس دن ہم ہرایک گروہ کو ان کے پیشواسمیت بلائیں گے.پھرجن کے دائیں ہاتھ میں بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ ان (کے اعمال)کی کتاب دی جائے گی.وہ(بڑے شوق سے )اپنی کتاب کوپڑھیں گے.اوران پر ذرّہ فَتِيْلًا۰۰۷۲ بھر (بھی)ظلم نہیں کیاجائے گا.حلّ لُغَات.فتیلًا.اَلْفَتِیْلُ:اَلْمَفْتُوْلُ.بٹی ہوئی چیز.حَبْلٌ دَقِیْقٌ مِنْ خَزَمٍ اَوْ لِیْفٍ کھجورکے ریشوں کی باریک بٹی ہوئی رسی.اَلسَّحَاۃُ الّتِیْ فِی شَقِّ النَّوَاۃِ.گٹھلی کے شگاف کاپردہ.مَافَتَلْتَہُ بَیْنَ اَصَابِعِکَ مِنَ الْوَسْخِ.و ہ قلیل سی میل جوہاتھوں کے درمیان بٹی جائے(اقرب)آیت کامطلب یہ ہے کہ ان پر ذرہ
Page 398
ہاتھ سے کام کرنے کاخیال پیداہو ا.اسی طرح آئندہ نسلوں کوہوا.بعض ڈاکٹر دائیں ہاتھ کے استعمال کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ د ل بائیں طرف ہے بائیں طرف کے حصہ دماغ کی طرف خون نسبتًا زیادہ جاتاہے.اوروہ زیادہ طاقتور ہوتاہے.اور چونکہ دائیں طرف کادماغ بائیں طرف کے اعصاب سے کام لیتا ہے.اوربائیں طرف کادما غ دائیں طرف کے اعصاب سے.پس بائیں طرف کے دما غ کی زیادتی کی وجہ سے دائیں طرف کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں اوراس وجہ سے انسان دائیں طر ف کے اعضاء سے کام لینے کی طرف طبعاً راغب ہوتاہے.یہ توجیہ درست ہویاغلط ہمیں اس سے تعلق نہیں.ہمیں توبس اتنی بات سے تعلق ہے کہ دائیں کوبائیں پر سب دنیا ترجیح دیتی آئی ہے.اوردائیں بازو سے کام لینا ایک طبعی تقاضاہے.دائیں بائیں کے فرق کے متعلق ایک اورعجیب بات بھی قابل غور ہے.علم اعداد وشمار سے معلوم ہواہے کہ صحیح الدماغ لوگوں میں سے صرف چار سے آٹھ فیصدی تک بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ ہیں.باقی سب دائیں ہاتھ سے کام لیتے ہیں.لیکن مجنونوں میں یہ نسبت بہت بڑ ھ جاتی ہے.اس سے بھی اس امر کاثبوت ملتاہے کہ قانون قدرت نے دائیں کوبائیں پر فضیلت دی ہے.(انسائیکلو پیڈیا برٹینکا جلد گیارہ زیرلفظ ہینڈڈنس) اوپرکے حوالہ جات سے یہ امر ثابت ہوجاتا ہے کہ دایاں ہاتھ کا م کرنے کے لئے زیادہ موزوں ہے.اوراکثر افراد عالم اسی ہاتھ سے کام کرتے ہیں.پس دایاں بازو قو ت عملیہ کا نشان قراردیاجاسکتاہے.اورقرآن کریم میں نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے کاجہاں جہاں ذکر ہے درحقیقت اس سے اسی طر ف اشارہ کرنامقصود ہے کہ وہ لوگ کام کرنے والے ،محنت کرنے والے اورقربانی کرنے والے تھے.اوربائیںہاتھ میں اعمال نامہ دینے کا جہاں جہاں ذکر ہے.اس سے اس طرف اشارہ کیاگیاہے کہ وہ لوگ نکمے قربانی سے بچنے والے اورسست تھے.کیونکہ بایاں ہاتھ بہت کم کا م کرتاہے.ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے.کہ دایاں ہاتھ اسلامی شریعت نے پاکیزہ کاموں کے لئے ،اوربایاں ہاتھ گندگی کی صفائی وغیرہ کے لئے تجویزکیا ہے.پس دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے سے یہ مراد بھی ہوسکتی ہے کہ تم لوگ پاکیزہ کام کرتے تھے.اوربائیں میں اعمال نامہ دینے سے مراد ہے کہ تم ناپاک کام کرتے تھے.دائیں کے لفظ سے ایک اورامر کی طرف بھی اشارہ ہوتاہے.قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کے متعلق لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ آتا ہے (الحاقۃ :۴۶)جس کے معنے مفسرین نے کئے ہیں.بِالْقُدْرَۃِ وَالطَّاقَۃِ.یعنی ہم ا س کو
Page 399
مضبوطی سے پکڑ لیں گے (قرطبی سورۃ الحاقۃ لاخذنا منہ بالیمین).پس دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ دینے سے اس طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے مضبوطی سے نیکی کوپکڑاتھا اس لئے نجات پاگئے.اورجن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیاجائے گا،انہیں یہ بتایاجائے گاکہ تم نے نیکی اورتقویٰ کے لئے پورے زورسے کوشش نہ کی تھی.اورگویابایا ںہاتھ جو کمزور ہوتاہے استعمال کیا تھا.اس لئے آج تمہاراانجام خراب ہواہے.علاوہ ازیں یُـمْن برکت کوبھی کہتے ہیں.(اقرب) حدیث میں خدا تعالیٰ کے متعلق آتاہے.کِلْتَایَدَی رَبِّی یَمِیْنٌ کہ میرے رب کے دونوںہاتھ برکت والے ہیں.اس کاکوئی شمال نہیں.پس دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے سے اس طرف اشارہ ہوگا کہ تمہاراانجام بابرکت ہوا.فَاُولٰٓىِٕكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ سے مراد یہ ہے کہ جسے انعام ملتاہے وہ خوب شوق سے اپنے فیصلہ کو پڑھتاہے لیکن جسے سزاملتی ہے وہ اپنے فیصلے کو پڑھنے کی تاب نہیں لاتا.اورحتی الوسع اس کے پڑھنے سے گریز کرتا ہے.وَ لَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا.فتیل تاگہ کو بھی کہتے ہیں.کیونکہ وہ بٹاجاتاہے.اورکھجور کی گٹھلی کے سوراخ میں جوجھلی ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں.استعارۃً تھوڑی سی چیز کے لئے بھی بولاجاتاہے.پس آیت کامطلب یہ ہے کہ ان پر ذرہ بھر ظلم بھی نہ کیاجائے گا.وَ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَ اورجواس (دنیا)میں اندھارہے گا وہ آخرت میں(بھی )اندھا (ہوگا)اور(اسی طرح وہ)اپنے (طورو)طریق اَضَلُّ سَبِيْلًا۰۰۷۳ میںسب سے بڑھ کر بھٹکاہواہوگا.تفسیر.دل کے اندھے قیامت کے دن دیدار الٰہی سے محروم رہیں گے جواس جگہ اندھاہے و ہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا.یعنی جس شخص نے یہاں پر روحانی آنکھوں سے کام نہیں لیا وہاںپر بھی اسے روحانی آنکھیں نہیں ملیں گی اوردیدارالٰہی سے محروم ہوگا.قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے.قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآىِٕرُ مِنْ رَّبِّكُمْ١ۚ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا (انعام :۱۰۵)کہ تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طر ف سے آگئے ہیں جودیکھے گافائدہ پائے گا.اورجونہ دیکھے گاوہ نقصا ن اٹھائے گا.پھر فرمایا وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ
Page 400
لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا(الفرقان :۷۴)یعنی مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا ذکر کیا جائے تو و ہ ان کی طرف بہرے اوراندھے ہوکر توجہ نہیں کرتے بلکہ کان اورآنکھیں کھو ل کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں.اس آیت میں ان کوبھی اندھا کہا ہے جوکسی بات کو بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں.پھر فرمایا ہے وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى (طٰہٰ:۲۵)یعنی کسی شخص کاآیات سے منہ پھیرناہی اس کااندھاہوناہے.غرض اعمٰی و ہ ہے جوحقیقت اوران بصائر کو جوخدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں.نہ دیکھے توایساشخص وہاںبھی خدا تعالیٰ کادیدار نہ کرسکے گااوراندھا رہے گا.کیونکہ اس نے دنیا میں اپنی مرضی سے اپنے لئے اندھا ہونا پسند کیاتھا.اس آیت کایہ مطلب نہیں کہ دنیاوی اندھے اگلے جہا ن میں بھی اندھے ہوں گے جسمانی نقص توبعث بعد الموت کے وقت سب کے سب دور ہوجائیں گے.کیونکہ پہلاجسم ہی یہاں رہ جائے گا.پس اس سے مراد روحانی اندھاپن ہے.وَ اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ۠ عَنِ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ اورقریب تھا کہ وہ اس (کلام )کی وجہ سے جوہم نے تجھ پر وحی سے نازل کیا ہے تجھے (سخت سے سخت )عذاب میں لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ١ۖۗ وَ اِذًا مبتلاکرتے ،تاکہ تو(ان سے ڈر کر)اس (کلام)کے سواکچھ اور(اپنے پاس سے )گھڑ کر ہماری طرف منسوب لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا۰۰۷۴ کرے.اور(اگر تم ایسا کرتے تو) اس صورت میں وہ یقیناًتجھے (اپنا )گہرادوست بنالیتے.حلّ لُغَات.خلیل خَلِیْلٌکے معنی ہیں اَلصَّدِیْقُ الْمُخَتَصُّ.خاص کیا ہوادوست.وَقِیْلَ ھُوَ الَّذِی صَادَقْتَہُ بَعْدَ اِذْ جَرَّبْتَہٗ اوربعض کہتے ہیں کہ خلیل اس دوست پر بولتے ہیں کہ جس کاتجربہ کرلینے کے بعد اس سے دوستی ڈالی جائے.(اقرب) تفسیر.اس آیت کی تفسیر میں مفسرین بعض روایات لکھتے ہیں جن کامفہوم یہ ہے کہ کفار نے رسول کریم
Page 401
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ اگر آپ ہمارے بتوں کوادب سے چھو لیں توہم آپ کے ساتھ ہوجائیں گے اس پر نعوذباللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال گذراکہ اللہ تعالیٰ کوتو میرے توحید کے عقیدہ کاعلم ہے.اگر میںا س طرح کرلو ں اورقوم کوہدایت ہوجائے توکیا حرج ہے.(فتح البیان زیر آیت ھذا) یہ معنے اس آیت سے ہرگز نہیں نکلتے اورنہ رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق یہ معنے ہیں اورعلاوہ ازیں اگلی آیات ا س مضمون کے بالکل الٹ مضمون کو بیا ن کررہی ہیں.کَادَ کے لفظ کا استعمال اس آیت میں کَادَ کالفظ آیا ہے.کاد کالفظ جب استعمال کیاجائے تواگر وہ مثبت ہوتو معنے یہ ہوتے ہیں کہ کَادَ کے بعد کافعل نہیں ہوا.اوراگرکاد سے پہلے نفی کاحرف آئے تو کاد کے بعد کے فعل کے متعلق یہ سمجھاجاتاہے کہ وہ فعل ہوگیا (مفردات).اس آیت میں کاد مثبت استعمال ہواہے.اس لئے کاد کے بعد کے فعل کے متعلق یہ سمجھا جائے گاکہ و ہ فعل صادرنہیں ہوا.اس آیت میں کَادَ کے بعد لَیَفْتِنُوْنَکَ کے الفاظ ہیں.پس کاد کے استعمال کے مطابق اس آیت کایہ مطلب ہوگا کہ فتنہ کافعل صادر نہیں ہوا.فتنہ کے معنے ابتلاء میں ڈالنے کے بھی ہوتے ہیں (اقرب).اور اس کے معنے عذاب میں مبتلاء کرنے کے بھی ہوتے ہیں.اگر اس کے معنے ابتلاء میں ڈالنے کے لئے جائیں توآیت کے یہ معنے ہوں گے کہ قریب تھا کہ کفار تجھے ابتلا ء میں ڈال دیتے.مگر وہ ڈال نہ سکے اوراگر فتنہ کے معنے عذاب کے کئے جائیں تومعنے یہ ہوں گے کہ قریب تھا کہ یہ لوگ تجھ کو عذاب میں ڈال دیتے مگروہ اس میں کامیاب نہیں ہوسکے.ابتلاء کے معنوںسے اس طرف بھی اشارہ نکلتاہے کہ گویا قریب تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے دبائوکومان کرقرآن میں تبدیلی کرنے پرتیار ہوجاتے.گوآپ نے ایساکیانہیں.ظاہر ہے کہ یہ معنے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں.کسی شریف آد می کی نسبت یہ کہناکہ قریب تھا کہ و ہ چوری کرلیتا.قریب تھا کہ وہ ظلم کرتا.قریب تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو پیٹتا یقیناً اس کی ہتک کرنے والا فقرہ ہے پس خداکے رسو ل کی نسبت یہ کہناکہ قریب تھا کہ وہ خدا پر افتراء کرلیتا بالکل غلط اورخلاف واقعہ ہے.مفسرین کااس امر پر خوش ہوجانا کہ آپ نے ایساکیا تونہیں کافی نہیں.کیونکہ خداکے نبی بدی کے قریب بھی نہیں جاتے.اورخدا تعالیٰ پر افترا ء توایسا فعل ہے کہ ایک ادنیٰ مومن کے متعلق بھی شبہ نہیں کیاجاسکتاکہ اس کاارتکاب توالگ رہا اس کے قریب بھی جائےگا.پس میرے نزدیک اس قسم کے معنے کرنے میں قدیم و جدید مفسرین نے سخت غلطی کی ہے.اس آیت کے معنی آنحضرت ؐ کی شان کے مطابق میرے نزدیک اس آیت میں فتنہ کے معنے عذاب
Page 402
کے ہیں اورعن کالفظ تعلیل کے معنوں میں آیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ پر بھی ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہواہے فرماتا ہے کفار نے کہا کہ وَ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْۤ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ (ھود:۵۴)ہم تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کونہیں چھوڑ سکتے.عن کے یہ معنے لےکر آیت کایہ مطلب بنے گا کہ قریب تھا کہ کفار تجھ کو اس کلام کی وجہ سے جو تجھ پر وحی کیا گیاہے عذاب میں مبتلاکرتے.اوران کی غرض ایساکرنے کی یہ ہوتی.کہ توہم پر افتراء کرکے قرآن کی تعلیم کے خلاف کوئی اورتعلیم بیان کرے.ان معنوں کے روسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کوئی حرف نہیں آتابلکہ اس میں یہ بتایا گیاہے کہ کفار کے ارادے تیر ے متعلق بڑے بڑے سخت تھے و ہ چاہتے تھے کہ تجھے پکڑ کر سخت عذابوں میں مبتلاکریں اور ان عذابوں سے تجھے مجبور کریں کہ توقرآن کوچھوڑ کران کے مطلب کی بات بیان کرے.اس سارے مضمون میں رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل یااراد ہ فعل کا ذکر نہیں بلکہ سارا کا سارا فعل کفار کا ہے اوربتایاگیا ہے کہ کلام سے پھراناتوان کی طاقت میں نہ تھا.اس غرض سے عذاب دینے کے ارادہ سے بھی و ہ روکے گئے.اوراس اراد ہ میں بھی خدا تعالیٰ نے ان کوناکام رکھا.قرآن کریم میں کفارکے ان ارادوں کا ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں ذکر آیا ہے.وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ١ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (الانفال :۳۱) یعنی یاد کر اس وقت کو کہ کفار تیرے متعلق یہ ارادے کررہے تھے کہ تجھے قید کردیں یاتجھے قتل کردیں یاتجھے نکال دیں.و ہ تیرے ذلیل کرنے کی تدبیریں کررہے تھے اوراللہ اپنی تدبیروں میں لگاہواتھا اوراللہ ہی بہتر تدبیر کرنے والا ہے.یعنی آخرخدا تعالیٰ کی تدبیرکامیاب ہوئی اورکفا ر کے ارادے باطل ہوئے.اس آیت سے ظاہر ہے کہ کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دبائو ڈالنے کےلئے قید،قتل اور جلاوطنی کے ارادے کررہے تھے.مگرخدا تعالیٰ نے ان کو ناکام رکھا.اسی مضمون کی طرف یہاں اشارہ ہے اوریہاںبھی یہی بتایا گیاہے کہ کفار عذاب دینے کے ارادہ میں ناکام رہے.کفار مکہ اپنے سب ارادوں میں ناکام رہے اس جگہ یہ کہا جاسکتاہے کہ قید اورقتل کے ارادوں میں تووہ ناکام ہوئے مگر اخراج کے ارادہ میں توکامیاب ہوگئے.توا س کا جواب یہ ہے کہ اس اراد ہ میں بھی وہ ناکام رہے کیونکہ کفار کااراد ہ یہ نہ تھا کہ آپؐ کو صرف وہاںسے نکال دیں.کیونکہ اس سے ان کی غرض پوری نہ ہوتی تھی.ان کاارادہ تویہ تھاکہ ذلیل کرکے نکالیں تادنیا میں آپ کی بدنامی ہو.مگراللہ تعالیٰ نے آپؐ کو قبل از وقت خبر دےدی اورآپ خود ہجرت کرگئے اوریہ امر ان کی سازش کے مطابق نہ تھا.بلکہ خلاف تھا.یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب معلو م کیا کہ آپ عزت کے ساتھ ہجرت کرگئے ہیں توآپ کاتعاقب کیا اورجب خود پکڑنے میں کامیاب نہ ہوئے
Page 403
توآپ کو پکڑ کر لانے والے کے لئے سو اونٹ کاانعام مقرر کیا.(بخاری کتاب المناقب باب ہجرۃ النبی صلعم )اگر صرف نکال دینا ان کے ارادوں میں شامل ہوتا توآپؐ کے جانے پر وہ لوگ خوش ہوتے.نہ یہ کہ آپ کاتعاقب کرتے اورپھر آپ کے پکڑ لانے والے کے لئے انعام مقررکرتے.پس کفار کاآپؐ کی ہجرت کے بعد کافعل بتاتاہے کہ وہ آپ کے نکل جانے کوکافی نہ سمجھتے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ آپ کو اس طرح ذلیل کرکے نکالیں کہ یاتوآپ نعوذ باللہ اپنی تعلیم سے باز آجا ئیں یاآپ کی ایسی سُبکی ہو کہ جس جگہ جائیں و ہ داغ آپ کے ساتھ جائے اوراس اراد ہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام رکھا.خلاصہ کلام یہ کہ یہ سورۃ ہجرت کے قریب کی ہے جس وقت کفار مقابلہ سے ہر طرح عاجز آکر مایوسی کے جوش میں اس بات پر تُل گئے تھے کہ قید کرکے ،قتل کی دھمکی دے کر یا ذلیل کرکے نکالنے کاڈراوادے کر آپ کوقرآن کی تعلیم سے پھرائیں اوراگر ا س کااثر نہ ہوتو پھر اپنے بدارادوں کو مکمل کرکے آپ کی جسمانی یااخلاقی زندگی کاخاتمہ کردیں.مگراللہ تعالیٰ نے ان کو اس اراد ہ میں بری طرح ناکام رکھا اوراسی ناکامی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیاگیاہے نہ اس امر کی طرف کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمزور ی آسکتی تھی یاآنے کاامکا ن تھا.وَ اِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا میں یہ بتایاہے کہ اگریہ عذاب دے کرتجھے سچائی سے پھرانے میں کامیاب ہوجاتے توتجھے اپنادوست بنالیتے.اس میں بھی کفار کی ہی اخلاقی حالت کوبیان کیاگیاہے نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کمزوری کو.کفار باربار کہتے تھے کہ اگرمحمد رسول اللہ صلعم اپنی تعلیم میں کفار کی خاطر کچھ بھی نرمی کرلیں تووہ انہیں اپنا سردار بنالیں گے.چنانچہ ایک دفعہ ان کاوفد آپ کے چچا ابوطالب کے پاس آیا اوریہ تجویز کی کہ ہم اب بھی یہ نہیں کہتے کہ محمد(صلعم)شرک کرے بلکہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معبودوںکوبُرانہ کہے.اگر یہ اتنا ہی کردے توہم اسے اپناسردار بنالیں گے (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام باب مباداۃ رسول اللہ قومہ وما کان منہم).انہی واقعات کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے اوربتایا ہے کہ جب لالچ دے کرکامیاب نہ ہوسکے توانہوں نے ظلم کرکے تجھے مجبورکرنے کااراد ہ کیا.مگرخدا تعالیٰ نے اس میں بھی انہیں ناکام رکھا.اورناکام رکھے گا.مگران کے یہ ارادے خود ان کے اخلاق پر جوروشنی ڈالتے ہیں و ہ ان کے لئے کیسی شرمناک ہے.ان کی یہ کوششیں بتاتی ہیں کہ انہیں تیری عظمت کااقرار ہے.تبھی توکسی نہ کسی صورت سے تیری تائید حاصل کرناچاہتے ہیں.مگراس قسم کی تائید پر خوش ہونا نہایت پست اخلاق پر دلالت کرتاہے.
Page 404
وَ لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا اور(تیراتویہ حال ہے کہ )اگر ہم تجھے (قرآن دےکر )ثبات نہ بخشتے (اوروحی بھی تجھ پر نازل نہ ہوتی )توتُو(اس قَلِيْلًاۗۙ۰۰۷۵ صورت میں بھی اپنی فطر ت کی پاکیزگی کی وجہ سے )قریب ہوتا کہ ان کی طرف کچھ (چھوٹی چھوٹی )باتوں میں جھک جاتا (مگرعملاً پھر بھی ان کے ساتھ شامل نہ ہوتا ).حلّ لُغَات.ثَبَّتْنَاکَ ثَبَّتَ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے.ثَبَتَ کے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر۲۸.یَثْبِتُ ثَبَتَ کا مضارع ہے.جس کا مجرد ثَبَتَ ہے اور ثَبَتَ الْاَمْرُ عِنْدَ فُلَانٍ کے معنے ہیں تَحَقَّقَ وَ تَأَکَّدَ.کوئی امر کسی کے نزدیک یقینی طور پر ثابت ہو گیا.ثَبَتَ فُلَانٌ عَلی الْامْرِ.دَاوَمَہُ.کسی کام پر دوام اختیار کیا.وَاَثْبَتَہُ وَثَبَّتَہُ : جَعَلَہُ ثَابِتًا فِی مَکَانِہِ لَایُفَارِقُہُ.اور اَثْبَتَہُ اور ثَبَّتَہُ کے معنے ہیں اس کو اس کی جگہ پر ایسے طور پر ثبات بخشا اور مضبوط رکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے.سو ثابت کے معنے ہوں گے اپنی جگہ پر مضبوط رہنے والا.(اقرب) ترکن :تَرْکُنُ رَکَنَ سے واحد مخاطب کاصیغہ ہے اور رَکَنَ اِلَیْہِ کے معنے ہیں مَالَ اِلَیْہِ اس کی طرف مائل ہوا(اقرب)پس كِدْتَّ تَرْكَنُ کے معنے ہوں گے کہ تومائل ہو جاتا ہے.تفسیر.یہ آیت اس تشریح کی تائید کرتی ہے جومیں نے اوپر بیان کی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرہم نے تجھے ثبات نہ بخشا ہوتاتوپھر ممکن تھاکہ تُوتھوڑاسا ان کی طرف مائل ہوجا تا.یعنی ثبات اگر حاصل نہ ہوتاتب بھی توان لوگوں کے ساتھ پوری طرح نہ مل سکتاتھا بلکہ ایک خفیف سااشتراک تیرے اوران کے خیالات کاہوسکتا تھا.اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے روسے ثَبَّتْنٰكَ کے کیا معنے ہیں.قرآن کریم میں دوسر ی جگہ فرماتا ہے.يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ(ابراہیم :۲۸)یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کوقول ثبات یعنی وحی کے ذریعہ سے اس دنیا کی زندگی اورآخری زندگی کے اعمال پر ثابت قدم رکھتاہے.اسی طرح سورۃ فرقان میں فرماتا ہے.كَذٰلِكَ١ۛۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ (الفرقان:۳۳) یعنی کفار اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن یکد م کیوں
Page 405
نازل نہ ہوا.فرمایا ٹھیک ہے قرآن یکدم نازل نہیں ہوااوراس کی غرض یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کے دل کو مضبوط کریں اورقرآن کریم کو آہستہ آہستہ ناز ل کرکے اس کے دل کے گوشوں میں رچادیں.ان آیات سے معلوم ہوتاہے کہ تثبیت کاذریعہ کلام الٰہی کانزول ہے.پس لَوْلَااَنْ ثَبَّتْنَاکَ کے معنے یہ ہوں گے کہ اگرقرآن ناز ل کرکے ہم نے تیرے دل کو ایمان پر ثبا ت نہ بخشاہوتا توممکن تھا کہ توکچھ تھوڑاسا ان کی طرف جھکتا.آنحضرت ؐ کسی وقت بھی کفار کی طرف مائل نہیں ہو سکتے اس تشریح کے بعد یہ امر آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد آپ کفار کی طرف مائل ہوسکتے تھے.بلکہ بتایایہ گیاہے کہ قرآن کے نزول کے بعد توتیراان کی کوئی بات مانناناممکن ہے.اگرقرآن نہ بھی ناز ل ہواہوتا اور اللہ تعالیٰ کے منشاء کا کامل علم تجھے نہ ہوتاتب بھی تیری فطرت اتنی پاک تھی کہ مشرکانہ باتوں میں توان کے ساتھ شریک نہ ہوسکتا تھا.ہاںممکن تھاکہ وحی کی روشنی کے نہ ہونے کے سبب سے بعض چھوٹی چھوٹی باتوں میں توان کے طریق پر عمل کرلیتا.پس یہ آیت توانتہائی مدح کے مقام پر ہے اوراس میں یہ بتایا ہے کہ بغیر قرآن کے بھی کفار محمد رسول ا للہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ کامل اتفاق کی امید نہیں کرسکتے تھے.پھر قرآن کے نزول کے بعد وہ ایسی امید کیونکر رکھتے ہیں.اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ اوراگر (جیساکہ ان کاخیال ہے توہم پر افتراء باندھنے والاہوتا)تواس صورت میں ہم تجھے زندگی کابڑاعذاب لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا۰۰۷۶ اورموت کا بڑاعذا ب چکھاتے (اور )پھر توہمارے مقابل پر اپناکوئی (بھی )مددگارنہ پاتا.حلّ لُغَات.ضِعْفُ الْحَیٰوۃِ ضِعْفُ الْحیٰوۃِ وَضِعْفُ الْمَمَاتِ عربی میں کبھی درمیا نی مضاف الیہ کو حذف کرکے دوسرے مضاف الیہ کی طرف مضاف کی اضافت پھیر دیتے ہیں اس قانو ن کے مطابق یہاں ضِعْفُ عَذَابِ الْحَیٰوۃِ اورضِعْفُ عَذَابِ الْمَمَاتِ کے جملو ں کو درمیانی مضاف الیہ کو مخذو ف کرکے ضِعْفُ الْحَیٰوۃِ اورضِعْفُ الْمَمَاتِ کی صورت میں بدل دیاگیا ہے(اعراب القرآن للدرویش) نیز ضعف کسی چیز کی مثل یااس سے دگنی یاتگنی وغیر ہ کوکہتے ہیں.کم سے کم ایک مثل اورزیاد ہ خواہ کتنے گنے ہو.چونکہ اردومیں اس کاترجمہ نہیں
Page 406
ہوسکتا.اس لئے زیادتی پردلالت کرنے کے لئے بڑے کے لفظ سے ضعف کا ترجمہ کردیاگیا ہے.تفسیر.اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اگرتورسول نہ ہوتا اوربعض چھوٹی باتوں میں اپنی قوم کے ساتھ شامل ہوجاتا توپھر ان کو کیا فائدہ ہوتا.اس وقت توان کی نجات کا موجب تونہیںہوسکتا تھا بلکہ خود عذاب کامستحق ہوتا.پھر ان کو تیری تائیدسے کیافائدہ تھا.مطلب یہ کہ نبی کی سب عظمت کلام الٰہی کی وجہ سے ہوتی ہے.کفاراس امر کومحسوس نہیں کرتے اورسمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص لیاقت کاآدمی ہے اگر اپنی تعلیم میں تبدیلی کرے اورہمارے ساتھ مل جائے توہماری قوم شائد خاص ترقی کرجا ئے.حالانکہ ان کایہ خیال باطل ہے.نبی کوکمال وحی سے حاصل ہوتاہے.وہ وحی جاتی رہے توو ہ بھی دوسر ے آدمیوں کی طرح ہوجائے پس ایسی خواہشات محض لغو اوربے فائد ہ ہیں.یہاںپر ضعف کے معنے مثل کے ہیں اورمضاف حذف کردیاگیاہے گویااصل یو ںہے.مِثْلُ عَذَابِ الْحَیٰوۃِ مِثْلُ عَذَابِ الْمَمَاتِ یعنی جس طرح دوسروں کو دنیا کاعذاب اورآخرت کاعذاب ملتاہے.ویساہی اگر نبی خدا تعالیٰ کی وحی سے ہدایت پاکر خدا تعالیٰ کی رضاحاصل نہ کرے.تووہ بھی باقی قوم کی طرح عذاب میں پکڑاجائے.وَ اِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَ اوروہ یقیناًتجھے اس ملک سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا.کہ وہ تجھے نکال ہی دیں گے.اوراس اِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا۰۰۷۷ صورت میں و ہ تیرے بعد (خود بھی )تھوڑا(عرصہ)ہی (یہاں )رہیں گے.تفسیر.اِسْتَفَزَّہُ مِنَ الْاَرْضِ کے معنے زمین سے نکال دینے کے ہیں.پس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ قریب تھا کہ یہ لوگ تجھے اس زمین سے نکال دیتے.مگراس کے آگے فرماتا ہے ’’تاکہ یہ تجھے نکال دیں ‘‘.ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ استفزازکے معنے کچھ اورہیں ورنہ تکرار فضول لازم آتاہے.لیکن اگر لِيُخْرِجُوْكَ کے معنے معنوی اخراج کے لئے جائیں توتکرار نہیں رہتا.اس صورت میںآیت کے معنے یہ ہوں گے کہ یہ لوگ قریب تھا کہ تجھے ملک سے اس طرح نکال دیتے کہ اس کانتیجہ یہ ہوتاکہ توان کی قومی زندگی سے نکل جاتا یعنی تجھے ذلیل کرکے
Page 407
نکال دیتے جس کی وجہ سے تیرااثر عرب پرسے اٹھ جاتااورگویا تیرامعنوی طو رپر خاتمہ ہوجاتا.یہ معنے پہلی آیات کےساتھ بالکل مطابق آتے ہیں اور میرے نزدیک یہی مراد ہے اوربتایا یہ گیاہے کہ اگریہ اس ارادے میں کامیاب ہوجاتے کہ ہتک کرکے تجھے مکہ سے نکالتے تواس کانتیجہ یہ نکلتاکہ تیرے بعد جلد ہی عذاب میں مبتلاکرکے ان کوتباہ کردیاجاتا مگراللہ تعالیٰ نے فضل کرکے تجھے آپ ہی ہجرت کاحکم دےدیا اوران کو تیری ہتک کے گناہ سے بچاکر شدید سزاسے محفوظ کردیا اورتیر ی عزت کوقائم رکھ کر اپنی محبت کاثبوت دیا.سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَ لَا تَجِدُ (اورتجھ سے بھی )ان (گذشتہ انبیاء )کی طرح (سلوک ہوتا)جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے (رسول بناکر )بھیجاتھا.لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًاؒ۰۰۷۸ اورتوہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہ پائے گا.تفسیر.مخالفین کے ہتک آمیز سلوک سے ان پر توبہ کا دروازہ بند ہوجاتا ہے اس آیت میں یہ بتایاہے کہ ہماری یہ قدیم سے سنت ہے کہ جب کسی نبی کو اس کی قوم ہتک آمیز سلوک کرکے نکالتی ہے تواس پر توبہ کادروازہ قریباً بند ہو جاتا ہے اورسخت تباہ کردینے والے قومی عذاب میں مبتلاہوجاتی ہے.اس کی مثال قوم صالح ہے جنہوں نے صالح کی اونٹنی کومار کران کے تبلیغی سفروں کو بند کردیا یاپھر یہود ہیں کہ انہوںنے مسیح کو صلیب پر لٹکایااوراس کے بعد حضرت مسیح ؑ کوملک چھوڑناپڑا.یہ دونوں قومیں بالکل برباد کردی گئیں.قوم صالح توظاہری طور پر تباہ ہوگئی اوریہود اخلاقی اورسیاسی موت میں مبتلاہوگئے.اللہ تعالیٰ نے چونکہ عربوںکو ایسی موت سے بچانے کافیصلہ کیاتھاان کو اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہونے دیااورا س طرح اس عذاب سے بچالیا.
Page 408
اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ توسورج کے ڈھلنے(کے وقت )سے لےکر رات کے خوب تاریک ہوجانے (کے وقت )تک (کی مختلف گھڑیوں وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ١ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ میں)نماز کوعمدگی سے اداکیاکر.اورصبح کے وقت(قرآن )کے پڑھنے کوبھی (لازم سمجھ)صبح کے وقت كَانَ مَشْهُوْدًا۰۰۷۹ (قرآن )کاپڑھنایقیناً(اللہ تعالیٰ کے حضورمیں ایک )مقبول (عمل)ہے.حلّ لُغَات.دُلُوک.دَلَکَتِ الشَّمْسُ دُلُوْکًا:غَرَبَتْ.سورج غروب ہوگیا.اِصْفَرَّتْ سورج زرد ہوگیا.وَقِیْلَ مَالَتْ وَزَالَتْ عَنْ کَبِدِالسَّمَاءِ بعض نے کہا ہے کہ دَلَکَتِ الشَّمْسُ کے معنی سورج ڈھلنے کے ہیں.(اقرب) غَسَق.غَسَقَتْ عَیْنُہُ غسُوْقًا.دَمَعَتْ وَقِیْلَ انْصَبَّتْ.وَقِیْلَ اظْلَمَتْ.اس کی آنکھ ڈبڈبا آئی.بعض محققین لغت کے نزدیک اس کے معنی آنکھ کے بہنے یاآنکھ پر تاریکی چھاجانے کے ہوتے ہیں.غَسَقَ اللَّیْلُ غَسَقًا اِشْتَدَّ ظُلْمَتُہُ یعنی را ت سخت تاریک ہوگئی.اَلْغَسَقُ.ظُلْمَۃُ اَوَّلِ اللَّیْلِ اَوْدُخُوْلُ اَوَّلِہِ حِیْنَ یَخْتَلِطُ الظَّلَامُ.غسق رات کے پہلے حصے کی تاریکی کو کہتے ہیں یارات کی ابتداء میں تاریکی شروع ہونے کوغسق کہتے ہیں.(اقرب) مشھودا.مَشْھُوْدًایہ شَھِدَ سے اسم مفعول کاصیغہ ہے.شَھِدَ کالفظ کسی جگہ پر حاضر ہونے اوراس پر اطلاع پانے کے معنوں میں استعمال ہوتاہے کہتے ہیں شَھِدَ الْمَجْلِسَ شُھُوْدًا:حَضَرَہُ، وَاطَّلَعَ عَلَیْہِ کہ وہ مجلس میںحاضر ہوا.اوراس نے اسے دیکھا.شَھِدَاللہُ اَیْ عَلِمَ اللہُ وَقَبِلَ اللہُ جب اللہ تعالیٰ کے لئے شَھِدَ کالفظ استعمال ہو تواس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جانااوراسے قبول فرمایا.وَقِیْلَ کَتَبَ اللہُ.بعض کے نزدیک اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کولکھ لیا.(اقرب) تفسیر.ان آیات میں مسلمانوں کو آنے والی خطرناک مشکلات کامقابلہ کرنے کے لئے تیار کیاگیا ہے.
Page 409
ایک طرف ہجرت کے بعدان قوموں سے مقابلہ ہونے والاتھا.جوظاہر میں عبادت گذار تھیں.اورمسلمانوں کی سستی انہیں اعتراض کاموقعہ دے سکتی تھی.دوسری طرف مسلمانوں کو جلد فتوحات ملنے والی تھیں جس سے عبادات میں سستی ہوجاتی ہے.پس دونوں امو رکو ملحوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ہوشیار کیا.کہ دشمن کے طعن کا نشانہ اسلام کونہ بنانا.اورنہ سست ہوکر خدا تعالیٰ کے فضلوں کو کھو دینا.پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر اس آیت میں اس آیت میں پانچوں نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں.دلوک کے تین معنی ہیں.اورہرایک معنی کے روسے ایک ایک نماز کا وقت ظاہرکردیاگیا.(۱)مَالَتْ وَزَالَتْ عَنْ کَبِدِ السَّمَاءِ یعنی زوال کو دلو ک کہتے ہیں.اس میں ظہر کی نماز آگئی (۲)اِصْفَرَّتْ.جب سورج زرد پڑ جائے تواس کوبھی دلوک کہتے ہیں اسمیں نماز عصر کا وقت بتادیاگیا.(۳)تیسر ے معنی غَرَبَتْ یعنی غروب شمس کے ہیں اس میں نماز مغرب کا وقت بتایاگیاہے (۴)غَسَقِ الَّيْلِ کے معنی ظُلْمَۃُ اَوَّلِ اللَّیْلِ کے ہیں.یعنی رات کے ابتدائی حصہ کی تاریکی.اس میں نماز عشاء کا وقت مقرر کردیاگیا.(۵)قُرْاٰنَ الْفَجْرِ کہہ کر صبح کی نماز کاارشاد فرمایا.اس کے سواکوئی اورتلاوت صبح کے وقت فرض نہیں ہے.اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.احادیث میں آتاہے کہ آنحضر ت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا.کہ صبح کی نماز کے وقت دن کے فرشتے آتے ہیں اوررات کے فرشتے چلے جاتے ہیں.و ہ فرشتے جب خداکے پاس جاتے ہیں.تودریافت کرنے پرکہتے ہیں.کہ ہم جب دنیا میں گئے.توتیرے بندوں کونماز پڑھتے ہی دیکھا اورواپس آئے ہیں تونماز پڑھتے ہی چھوڑ کرآئے ہیں.عَنْ اَبِی ھُرِیْرَۃَ عَنِ النَّبِیِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ تَشْھَدُ ہُ مَلَائِکَۃُ اللَّیْلِ وَمَلَائِکَۃُا لنَّھَارِ.(الترمذی کتاب التفسیر باب سورۃ بنی اسرائیل)اس کامطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز خاص طورپر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے.اورخاص ہی طور سے مقبول ہوتی ہے کیونکہ ا س وقت انسان میٹھی نیند کو چھو ڑ کراٹھتاہے.صبح کی نماز دراصل عام مسلمان کی تہجد ہی کی نماز ہے.بلاشبہ جوانسان صبح کی نماز پڑھے گا.اگراس نے وہ نماز ایمانداری سے پڑھی ہوگی توباقی نماز یں بھی اس کے لئے آسان ہوجائیں گی.
Page 410
وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ١ۖۗ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ اوررات کو بھی تو اس(یعنی قرآن )کے ذریعہ سے کچھ سولینے کے بعد شب بیداری کیاکر.جوتجھ پر ایک زائدانعام رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا۰۰۸۰ ہے (اس طرح پر )بالکل متوقع ہے.کہ تیرارب تجھے حمد والے مقام پر کھڑا کردے.حلّ لُغَات.فَتَھَجَّدْ.ھَجَدَ یَھْجُدُ ھُجُوْدًا سے باب تفعل کا واحد مذکر امر کاصیغہ ہے.ھَجَدَ الرَّجُلُ: نَامَ بِاللَّیْلِ آدمی رات کوسویا.وَسَھِرَ رات کوبیداررہا.وَفِی اللِّسَانِ تَھَجَّدَ الْقَوْمُ: اِسْتَیْقَظُوْا لِلصَّلوٰۃِ اَوْغَیْرِھَا.لسان العرب میں لکھا ہے.کہ تَھَجَّدَ الْقَوْ مُ کے معنی لوگوںکے سونے کے بعدنماز وغیرہ کے لئے بیدار ہونے کے ہیں(اقرب) نافلۃً نَفَلَ.(یَنْفُلُ.نَفْلًا)الرَّجُلُ فُلَانًا :اَعْطَاہُ نَافِلَۃً مِنَ الْمَعْرُوْفِ مِمَّالَایُرِیْدُ ثَوَابَہُ مِنْہُ یعنی ایک شخص نے دوسرے پر ایسی بخشش کی جس کے بدلے کا اس سے خواہش مند نہیں.نَفَلَ الْاِمَامُ الْجُنْدَ : جَعَلَ لَہُمْ مَاغَنَمُوْا.امام نے لشکر کو مال غنیمت دے دیا.لفظ نافلہ نفل سے اسم فاعل مؤنث بمعنی مفعول ہے.یعنی دی ہوئی چیز.دیاہواانعام اَلنَّافِلَۃُ کے معنی(۱) اَلْغَنِیْمَۃُ.غنیمت.(۲)اَلْعَطِیَّۃُ.بخشش.(۳)مَاتَفْعَلُہُ مِمَّالَایَجِبُ.فرض سے زائدعمل کرنا.(۴)وَلَدُالْوَلَدِ.پوتا.اس کی جمع نَوَافِلُ آتی ہے (اقرب) تفسیر.تَـهَجَّدْ بِهٖ میں ہٖ کی ضمیر قرآن کریم کی طر ف پھر تی ہے اورمراد یہ ہے کہ اس نماز میں تلاوت قرآن پرخاص زورہونا چاہیے.تہجد کے معنے سوکراٹھنے کے ہوتے ہیں.اس لئے تہجد کی نماز سے پہلے سوناضروری ہے.جولوگ ساری رات جاگنے کے چلّے کھینچتے ہیں.وہ عباد ت نہیں کرتے.شریعت کے منشاء کو باطل کرتے ہیں.ایسی عباد ت قرآن کریم کے منشاء کے خلاف ہے.رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ہمیشہ پہلی رات سوتے تھے.اورآخر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے(بخاری کتاب التہجد باب من نام اول اللیل و احیا اخرہ).نماز محبوب کی زیارت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایاہے کہ عبادت کاموقعہ دینا ایک احسان الٰہی ہے.مگر افسوس ان لوگو ں پر جو نماز کوچٹّی سمجھتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اپنے رب کی زیارت
Page 411
ہے.اورزیارت الٰہی ایک انعام ہے.اورکوئی عقلمند انسان اپنے محبوب کی زیارت کوچٹّی نہیں سمجھے گا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے توعبادت کی شان ہی یہ بتائی ہے کَاَنَّکَ تَرَاہُ وَاِنْ لَمْ تَکُنْ تَرَاہُ فَاِنَّہُ یَرَاکَ (مسلم کتاب الایمان باب الاسلام ما ھو و بیان خصالہ) یعنی صحیح نماز یہ ہے کہ تو خدا تعالیٰ کودیکھ لے.یاکم سے کم نماز کے وقت یہ یقین ہوکہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے.پس اتنے بڑے انعام کو چٹی سمجھنا سخت ظلم ہے نماز اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ہے.میراتویہ عقید ہ ہے کہ انسان ایک نماز بھی چھوڑے تووہ نمازی نہیں کہلاسکتا.کیونکہ حکم اقامۃ الصلوٰۃ کا ہے.اوروہ دوام کوچاہتاہے.جب ایک بھی نماز چھوڑ دی گئی تودوام نہ رہا.نَافِلَۃً لَّکَ سے ا س بات کااظہار کیا گیا ہے.کہ عبادت کاموقعہ دینا ہماراایک احسان ہے.یاممکن ہے.کہ تہجد کی نماز پہلے انبیاء پرواجب نہ کی گئی ہو.ا س صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے.کہ یہ عبادت کاموقعہ خاص تیرے لئے انعام ہے.مَقَامًا مَّحْمُوْدًا میں عظیم الشان پیشگوئی مَقَامًا مَّحْمُوْدًا میں ایک بہت بڑی پیشگوئی کی گئی ہے.دنیامیں کسی شخص کو بھی اتنی گالیاں نہیں دی گئیں.جتنی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کودی گئیں ہیں.ڈاکو، بدکار، بدمعاش، فاسق سے فاسق انسان کو ان گالیوں کے کروڑویں حصہ کے برابربھی گالیا ں نہیں دی جاتیں.جتنی کہ آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو دی گئی ہیں.مقا م محمود عطا فرماکر اللہ تعالیٰ نے ان گالیوں کاآپ کوصلہ دیاہے.فرماتا ہے جس طرح دشمن گالیاں دیتا ہے.ہم مومنوں سے تیرے حق میں درود پڑھوائیں گے اسی طرح عرش سے خود بھی تیری تعریف کریں گے.اس کے مقابل پر دشمن کی گالیاں کیاحیثیت رکھتی ہیں.مقام محمود سے مرادشفاعت بھی ہے مقام محمودسے مراد مقام شفاعت بھی ہے.کیونکہ جیساکہ حدیثوں سے ثابت ہے.سب اقوام کے لوگ سب نبیوں کے پاس سے مایوس ہوکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے پاس شفاعت کی غرض سے آئیں گے.اورآپ شفاعت کریں گے(بخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالیٰ ذریۃ من حملنا مع نوح).اس طرح گویا ان سب اقوا م کے مونہہ سے آپ کے لئے اظہار عقیدت کروادیاجائے گا.جو اس دنیا میں آپ کو گالیاں دیتی تھیں.اوریہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا مقام محمود ہے.مقام محمود سے مراد خروج مہدی بھی ہے مقام محمود سے مراد میرے نزدیک خروج مہدی بھی ہے.کیونکہ اس کے ظہورکا وقت وہی بیان ہواہے.جب مسلمانوںکے اسلام سے روگردان ہوجانے کی اورکافروں کے کفر میںترقی کرجانے کی خبر دی گئی ہے.ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے اس پہلوان کاظہور جوان گالیوں کی روکو تعریف
Page 412
سے بدلوادے.مقام محمود کاہی ایک کرشمہ ہے.میں نے اسی خدمت میں حصہ لینے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے حالات بیان کرنے کے لئے سال میں ایک دن مقررکیا ہواہے جس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ اپنے ان تاثرات کو بیان کرتے ہیں.جوآپ کے حالات پڑ ھنے سے ان کے دلوں پر پڑتے ہیں.اقم الصلوٰۃ الآیتین.نماز پنجگانہ اورتہجد کے ذکر کے بعد جو مقام محمود کا ذکرکیا ہے.اس میں اس طرف اشار ہ ہے کہ جس شخص کے دشمن زیادہ ہو ںاوربدگولوگوں کی تعداد بڑھ جائے اس کایہ علاج نہیں.کہ وہ ان سے الجھتاپھرے.بلکہ ایسے وقت میں انابت الی اللہ اوربارگاہ الٰہی میں فریاد کرنا ہی ان فتنوںکودورکرتاہے.بلکہ اگرانابت بہت بڑھ جائے تومذمت تعریف سے اورگالیاں دعائوںسے بدل جاتی ہیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے ایسا ہی ہوا.کہ جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے تھے ایک دن عاشق صاد ق ہوگئے.عمرو بن عاص.خالد.عکر مہ.مردوں میں سے اور ہندہ عورتوں میں سے اس کی زبردست مثالیں ہیں.یہ لوگ آپ کی دعائوں سے ہی کھنچ کر آگئے.ورنہ جس قدر عداوت ان کے دل میں تھی.اس کادور کرنا انسانی بس کی بات نہ تھی.آنحضرت ؐ کی زندگی کا ہر واقعہ تاریخ میں موجود ہے بعض نادان کہتے ہیں کہ معلوم ہوتاہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی زندگی میں (نعوذ باللہ من ذالک) کوئی نقص تھا تب ہی تو آپ کو اتنی گالیا ںدی جاتی ہیں.میں کہتا ہوںیہ بات نہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو گالیاں کسی عیب کی وجہ سے نہیں.بلکہ حضور کی خوبیوں کی وجہ سے دی جاتی ہیں.دنیاکے کسی اورنبی کو تمام انسانوں کے لئے اسوہ حسنہ نہیں بنایاگیاتھا.اس لئے کسی نبی کی زندگی کے مکمل سوانح محفوظ نہیں کئے گئے.اگردنیا کے مذہبی پیشوائوں میں سے کسی پیشواکی زندگی کے حالات تفصیلاً موجود ہیں.تووہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں.آپ کی زندگی کاہرواقعہ تاریخ میں موجود ہے.آپ کاکھانا.آپ کاپینا.آ پ کاچلناپھرنا اور بولنا اوربیٹھنا غرض ہرحرکت و سکون آپ کا محفوظ کرلیا گیا ہے.گویا جس طرح سے کسی شخص کی تلاشی لی جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضورکے اعمال وخیالات کواکٹھاکرکے دنیا کے سامنے پیش کردیا ہے.اس کے باوجود آپ کے دشمنوں کے سامنے میدان میں جمے رہنا اورعقل سے کام لینے والوں کی نگاہ میں عزت پاجاناکوئی معمولی معجز ہ نہیں.اوراگریہ عزت جوپورے امتحان کے بعدحاصل ہوئی ہے مقام محمود نہیں کہلا سکتی توپھر کوئی اورعزت مقام محمود نہیں کہلاسکتی.حق یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے صرف ایک دن کے واقعات کے برابربھی دوسرے نبیوں کی عمر بھر کے واقعات محفوظ نہیں.پس ایسے مخفی وجودوں کی زندگی پر کوئی جرح کرے توکیاکرے.پس کسی قوم کااس پر خو ش ہوناکہ اس کے نبی پر اس قدراعتراض نہیں ہوتے کوئی معقول خوشی نہیں.
Page 413
ہے.یاوَ اجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ.(الشعراء:۸۶ ) مجھے ظاہر و باطن طور پر اچھی تعریف حاصل ہو.یعنی میرا ذکر خیر کے ساتھ صرف لوگوں کی زبان پر ہی نہ ہو بلکہ واقع میں بھی میرے نیک کام دنیا میں قائم رہیں.اور میری تعریف جھوٹی نہ ہو یعنی لوگ غلو کرکے مجھ سے شرک نہ کرنے لگ جائیں.یا فرمایا ہے کہ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ مجھے اس طرح کا داخلہ عطا ہو جو ظاہر و باطن میں اچھا ہو اور میں اس طرح اپنے شہر سے نکلوں کہ جو ظاہر و باطن میں اچھا ہو.یعنی اس میں بزدلی اور کمزوری ایمان کا کوئی شائبہ نہ ہو.اورا س کے نتائج نہایت اعلیٰ ہوں.پس مُدْخَلَ صِدْقٍ کے معنے ہوںگے ظاھراً وباطناً اچھے طورپر داخل کرنا.تفسیر.صِدْقٍ کے معنی بتائے جاچکے ہیں یعنی اندرونی وبیرونی دونوں حالتیں یکساں طور سے اچھی ہوں اس آیت میں دعااور انابت کے جواب میں جومقام محمود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کوملنے والے تھے.ان میں سے پہلے مقام محمود کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اب تجھے اسراء کی خبر کے ماتحت مکہ سے نکال کر ہم ایک اورجگہ کی طرف جو مقام محمود ہے لے جائیں گے.اس لئے اس کے متعلق ابھی سے دعائیں شرو ع کردے.اورکہہ کہ اے خدامجھے اس شہر میں ظاہری او رباطنی خوبیوں کے ساتھ داخل کر او راس مقام سے بھی جس میں میں اس وقت ہوں یعنی مکہ سے ظاہری اورباطنی خوبیوں کے ساتھ نکال یعنی کفار جواراد ہ کررہے ہیں.کہ مجھے ذلت سے نکالیں.جس سے میرارعب اور اثر جاتا رہے.اس میں وہ کامیاب نہ ہوں.چنانچہ یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو کفار اپنی مرضی کے مطابق نہ نکا ل سکے بلکہ خدا تعالیٰ کے علم دینے سے آپ خو د ہی مناسب موقعہ پر مکہ سے ہجرت کرگئے.اسی طرح آپ کادخول مقام محمود میں بھی نہایت اعلیٰ ہوا.اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کی شمع رخ کے ہزارو ں پروانے پیداکردیئے.جو آپ کےمونہہ کی طرف ہروقت دیکھتے رہتے تھے.اورجن کو آپ سے وہ عشق تھا.کہ اس عشق کی نظیر دنیا میں اورکہیں نہیں ملتی.ان معنوں پر ایک اعترا ض ہو سکتا ہے اوروہ یہ کہ خروج مکہ پہلے ہواہے.اوردخول مدینہ بعد میں.پھر قرآن کریم نے دخول کو پہلے کیوں بیا ن فرمایا.اس کا جواب یہ ہے کہ خروج کی خبر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو لازما ً تکلیف ہونی تھی.اوریہ خیال پیداہوناتھا کہ مکہ سے نکل کر ہم کہاں جائیں گے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی محبت کی وجہ سے اس امر کاپہلے ذکر فرمایاکہ عنقریب تجھ کوایک مبارک مقام ملنے والا ہے اورمکہ سے نکلنے کے ذکر کو اس کے بعد رکھا.تاکہ تسلی پہلے مل جائے اورغم کی خبر بعد میں ملے.
Page 414
دوسرے معنی اس آیت کے یہ بھی ہوسکتے ہیں.کہ دخول سے مراد آپ کادوبار ہ مکہ میں واپس آنا ہے.اورخروج سے مراد آپ کی ہجرت ہے.اس صورت میں بھی ترتیب کے متعلق اعتراض پڑے گا.کہ ہجرت پہلے تھی.اورفتح مکہ بعد میں.لیکن اس کابھی وہی جواب ہے.جوپہلے بیان ہوا.کہ مکہ سے نکلنے کے صدمہ کو اس خبر سے کم کردیا.کہ آپ پھر مکہ میں آنے والے ہیں.اوراس کے بعد مکہ سے نکلنے کا ذکر کیا.تاتسلی پہلے ہوجائے.اورغم کی خبر بعد میں بتائی جائے.اس صورت میں مقام محمود کے معنی یہ ہوں گے کہ فتح مکہ کے بعد دشمنوں کے سب اعتراضات دورہوجائیں گے.اورعربوں پر آپ کی سچائی ظاہرہوجائے گی.چنانچہ ایسا ہی ہوا.سُلْطَانًا نَصِیْرًا مجھے اپنے پاس سے ایساغلبہ دے.جو کہ نصیر ہو.یعنی وہ میرے کاموں میں میراممدو معاو ن ہو مضر نہ ہو کیونکہ بعض غلبے انسان کے لئے بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصا ن دہ ثابت ہوتے ہیں.یعنی مجھے غلبہ توملے.مگر ایسانہ ہو جس کاانجا م میرے کاموں کی تباہی ہو.ٍ یہ دعااسراء کے ان معنوں کی تائید کرتی ہے.جو میں اوپر بیا ن کرچکا ہوں اوراس سے معلو م ہوتا ہے کہ اسراء کے کشف کی ایک تعبیر مدینہ کی طرف ہجر ت کرنا تھی.وَ قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ١ؕ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ اور(سب لوگوں سے )کہہ دے (کہ بس اب )حق آگیا ہے.اورباطل بھاگ گیا ہے اورباطل توہے ہی بھاگ زَهُوْقًا۰۰۸۲ جانے والا.حلّ لُغَات.زھق.زَھَقَ الْبَاطِلُ کے معنےہیں.اِضْمَحَلَّ.باطل کمزور ہوگیا.الشَّیْءُ: بَطَلَ وَ ھَلَکَ.کوئی چیز بے اثر ہوگئی مٹ گئی (اقرب) تفسیر.اس میں یہ اشارہ کیاگیا ہے.کہ مدنی زندگی کے شرو ع ہونے کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی طاقت مضبوط ہوتی.اوربڑھتی جائے گی.اوردشمن کی کمزوری اورضعف و ناتوانی کے سامان پیدا ہوتے جائیں گے.یہاں تک کہ آخر باطل کمزورپڑتے پڑتے فناہوجائے گا.اورمکہ کی فتح کے وقت عرب سے بت پرستی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کردیاجائے گا.
Page 415
زھوق کا لفظ استعمال کرنے میں حکمت قرآن کریم کا یہ بے نظیر کما ل ہے کہ وہ ہرموقعہ کے لئے ایسے الفاظ چنتاہے جوایک لمبے مضمو ن پر دلالت کرتے ہیں.اس آیت میں زَھَقَ کالفظ رکھا ہے.اس کی جگہ ھَلَکَ اور بَطَلَ وغیرہ الفاظ بھی رکھے جاسکتے تھے.مگر ان سے باطل کی تباہی کی اس تدریج کاعلم نہ ہوتا.جوزھوق کے الفاظ سے بتائی گئی ہے.زھو ق کے معنی کمزور ہوجانے او رہلا ک ہوجانے کے ہیں.اوراسی طرح مکہ والوں سے گزری یہ نہیں کہ وہ یکد م تباہ ہوگئے.بلکہ کمزو رہونے شروع ہو ئے پھر آہستہ آہستہ و ہ وقت آیا کہ بالکل فنا ہوگئے.پس زھوق کے لفظ نے ہلاکت کی تفصیل بھی بتاد ی.جب مکہ فتح ہوااورخانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کوتوڑتوڑ کر پھینکا گیا.اس وقت رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے جاتے تھے.ایک ایک بت پر ضرب لگاتے اورفرماتے جاتے تھے.جَآءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَھُوْقًا(بخاری کتاب المغازی باب این رکز النبی الرایۃ یوم الفتح).یہ بھی قرآن کامعجزہ ہے کہ اس نے کعبہ سے بتوں کے دورکئے جانے کے موقعہ کے لئے جوآیت رکھی ہے.و ہ شعر کی طرح موزوں ہے.اس قسم کی خوشی کاموقعہ انسانی طبیعت کو شعر کی طرف راغب کرتا ہے.قرآ ن شعر نہیں مگراس کی آیات کے بعض ٹکڑے شعرکی سی موزونیت رکھتے ہیں.یہ آیت بھی اگراس کے شروع سے قل کالفظ اڑادیاجائے توشعر کی طرح موزوں ہوجاتی ہے.جَآءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُایک مصرعہ اوراِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا.دوسرامصرعہ ہوتاہے.قل نے اس کو شعرکی تعریف سے نکا ل دیا.لیکن جب ا س کے پڑھنے کاموقعہ آیا توچونکہ اس آیت کو قل کے بغیر پڑھناتھا اس وقت یہ آیت اپنے شاندا رمعانی کے علاوہ ایک موزوں کلام کابھی کام دیتی تھی.اوراس خوشی کے موقعہ کے عین مناسب حال تھی.جَآءَ الْحَقُّ وَزَھَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَھُوْقًا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کویہ آیت پڑھتے دیکھ کر صحابہ کس طرح لہریں لے لے کر اس آیت کو پڑھتے ہوں گے اورکس طرح ان کے ایما ن ہرلحظہ او رہرمنٹ بڑھتے ہوں گے.ا س کاانداز ہ اصحاب ذوق ہی لگاسکتے ہیں.
Page 416
وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ١ۙ اورہم قرآن میں سے آہستہ آہستہ وہ( تعلیم) اتاررہے ہیں جو مومنوں کے لئے (تو)شفاء اوررحمت (کاموجب ) وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا۰۰۸۳ ہے.اورجو ظالموں کو صرف خسار ہ میں بڑھاتی ہے.حل لغات.خسارًا.خَسَارًاخَسِرَ کامصد رہے خَسِرَ التَّاجِرُ فِیْ بِیْعِہِ کے معنے ہیںتاجرکو اپنی تجارت میں گھا ٹا ہوا.خَسِرَ الرَّجُلُ.ضَلَّ گمراہ ہوگیا.ھَلَکَ.ہلاک ہوگیا (اقرب) تفسیر.اس کامطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز مختلف نظروں سے دیکھی جاتی ہے.اورجیسی کسی کی فطرت ہوتی ہے.ایسا ہی و ہ دوسر ی چیز وں کو سمجھتاہے.کتناہی اعلیٰ اورپاک کلام کیوں نہ ہو.لیکن گندے دل والے انسان کو اس میں گند ہی نظرآتے ہیں.میں یہ دیکھ کرحیران رہ جاتاہوںکہ پنڈت دیانند صاحب کو قرآن مجیدکے ابتداء سے لےکر آخر تک اعتراض ہی اعتراض نظرآئے.اورانہیں کوئی خوبی اس میں دکھائی نہ دی (ستیارتھ پرکاش باب ۱۴) یہی معنی اس آیت کے ہیں.کہ ظالم اس پر نکتہ چینیا ں کرکے اور بھی اپنے گناہوں کو بڑھاتے ہیں.ان عام معنوں کے علاوہ میرے نزدیک اس آیت کے یہ معنی بھی ہیں.کہ اس جگہ قرآن سے مراد وہ خاص حصہ ہے جوپہلے اترچکا ہے.یعنی مومنوں کی ترقی اورکامیابی کی پیشگوئیاں اوردشمنوں کی بربادی اور تباہی کی خبریں.فرمایا کہ ان خبروں کے پوراہونے کا وقت آگیا ہے.ان پیشگوئیوں کے نتیجہ میں مسلمانوں کے زخمی دلوں کو شفاحاصل ہوگی.اوران کے زخم مندمل ہو ں گے.ان کے ترقی کے سامان پیداہوں گے مگریہی پیشگوئیاں کافروں کے حق میں نقصان اور تباہی کے سامان ساتھ لائیں گی.
Page 417
وَ اِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ١ۚ وَ اِذَا اور جب ہم انسا ن پر انعام کریں تووہ روگردان ہو جاتاہے اوراپنے پہلو کو (اس سے )دور کرلیتا ہے.اورجب اسے مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا۰۰۸۴ تکلیف پہونچے تو وہ بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے.حلّ لُغَات.نَاٰبِجَانِبِہ.نَاٰ کے معنے ہیں بَعُدَ دور ہوا.ب لازم فعل کو متعدی بنانے کے لئے ہے پس نَاٰ بِجَانِبِهٖکے معنی ہوںگے اس نے اپنے پہلو کو دورکرلیا (اقرب) یؤُسًا.یؤُسًایہ یَئِسَ سے مبالغہ کاصیغہ ہے.یؤُوْسٌ کے معنی ہیں بہت مایوس ہونے والا(اقرب).تفسیر.اس میں بتایا کہ مومن اور کافر میں بڑافرق ہے.مسلمانوں نے متواتر تیرہ سال تک مشکلات اورمصائب برداشت کئے.ماریں کھائیں اورعذاب سہے مگر اف تک نہ کی.لیکن ان کافروں پر جب عذاب شرو ع ہوگااورمومنوں کی ترقی کے سامان ہوں گے تویہ کفار اسی دن ہتھیا ر ڈال دیں گے اورناامید ہوجائیں گے.چونکہ کافرکو خدا پر ایمان نہیں ہوتا.اس لئے و ہ ذراسی تکلیف سے بھی گھبراجاتاہے.مگرمومن خداکے لئے سب کچھ دلیری اورجرأت سے برداشت کرتاہے.قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ١ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ تو(انہیں)کہہ(کہ ہم میں سے )ہرایک (فریق )اپنے (اپنے)طریق پر عمل کررہا ہے پس (اپنے رب پر ہی اَهْدٰى سَبِيْلًاؒ۰۰۸۵ فیصلہ چھوڑ دو.کیونکہ ) تمہارا رب اسے جو زیاد ہ صحیح راستہ پر ہے بہترجانتا ہے (اس لئے اس کافیصلہ سچے کی سچائی کو ضرور روشن کردےگا ).
Page 418
حلّ لُغَات.شَاکِلَتِہٖ.شَاکِلَۃٌ اس کامادہ شَکَلَ ہے.اس کے معنی یہ ہیں اَلشَّکْلُ.صورت.شکل.اَلنَّاحِیَۃُ.طرف.اَلنِّیَّۃُ.نیت.اَلطَّرِیْقَۃُ.طریق.اَلْمَذْھَبُ.راستہ.مذہب.اَلْحَاجَۃُ.ضرورت (اقرب) تفسیر.فرماتا ہے منکرین سے کہہ دے کہ ہرشخص اپنے اپنے طریق پراوراپنی اپنی شکل و صورت اپنی اپنی قابلیت.اپنے اپنے دین اور اپنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتاہے.مومن کی نیت چونکہ خدا تعالیٰ کاحصول ہوتی ہے.اس لئے وہ دنیا کے چلے جانے پرگھبراتانہیں.بلکہ سب ابتلائوں کادلیری سے مقابلہ کرتا ہے.لیکن کافرچونکہ دنیا پرست ہوتاہے او راس کاساراعمل دنیا کی خاطر ہوتاہے جب وہ دنیا کو جاتے دیکھتاہے توگھبراکرہتھیار ڈال دیتاہے.فرمایا تمہارارب خو ب جانتا ہے کہ کون ہدایت کی راہ پر عمل کررہا ہے.یعنی خدا تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویساہی سلوک کرتاہے.جیسی کہ اس شخص کی نیت ہوتی ہے.فرمایاہم عمل کوبھی دیکھیں گے اورنیت کوبھی.اورپھر دونوں کے مطابق معاملہ کریں گے.جوخدا تعالیٰ کی رضاکو مدنظررکھیں گے اوراس کے دین کے لئے قربانیاں کریں گے.ان کی تائید ونصرت کی جائے گی.میں نےپچھلی آیات کی تفسیر میں کفار مکہ کومدنظر رکھا ہے لیکن یہی مضمون یہود کے متعلق بھی چسپا ں ہوتاہے.اوروہ بھی اس میں شامل ہیں.انہوں نے بھی مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامقابلہ کیا.اورآخر تباہ وبرباد ہوئے.اورخیبر کی جنگ کے بعد ان کاعرب سے صفایا ہوگیا(تاریخ الخمیس جلد ۲ صفحہ ۵۲).اور انہوں نے بھی دعوے توبڑے کئے مگر جب مسلمان مجبو رہوکر دفاع کے لئے کھڑے ہوگئے تواس طرح بزدلی سے ہتھیار ڈال دئے کہ ہمیشہ تاریخ ان کی بزدلی کی داستان بطور مثال قائم رکھے گی.وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ١ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَ مَاۤ اورو ہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں تو(انہیں )کہہ(کہ )روح میرے رب کے حکم سے (پیداہوئی)ہے اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا۰۰۸۶ اور تمہیں (اس کے متعلق )علم سے کم ہی (حصہ )دیا گیاہے.حل لغات.الرُّوح الرُّوحکے لئے دیکھو حجرآیت نمبر ۳۰.تفسیر.روح کے متعلق مفسرین کے اقوال یہ روح جس کے متعلق سوال کیا گیاہے کیا چیز ہے ؟
Page 419
مفسرین نے اس کی مختلف تاویلیں کی ہیں بعض نے اس سے جبرائیل مراد لیا.اوربعض نے اس سے مراد قرآ ن کریم کو لیا ہے.کیونکہ اس سے پہلے بھی اوربعد میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے (بحر محیط زیر آیت ھذا)بعض نے وہ فرشتہ مراد لیا ہے جس کے سپرد دنیا کی پیدائش ہے.بعض نے کہا ہے کہ ہر ایک فرشتہ کوروح کہتے ہیں.اوربعض کے نزدیک ایک خاص فرشتہ ہے.جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی تسبیح کے لئے پیدا کیا ہے بعض نے تواس روایت کو صحابہ رضوان اللہ علیہم تک پہونچایا ہے کہ اس کے سوسر ہیں.ہرایک سر میں سو مونہہ ہیں.اورہرایک مونہہ میں سوزبان ہے.اور ہرایک زبان سوسوبولی میں خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے(تفسیر ابن جریر زیر آیت ھذا).انہوں نے غالباً اس روایت کو بیان کرکے سمجھ لیا ہے کہ شاید اس طرح خدا کی تسبیح کاحق پوراہوجائے گا.حالانکہ اس تسبیح سے زیادہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی امت ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کررہی ہے.سار ی دنیا میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں.ہزاورں بولیا ں بولتے ہیں.اورہرزبان میں آپ کی تعریف کررہے ہیں.استاذی المکر م حضرت مولوی نورالدین صاحبؓ اس جگہ روح کے معنی کلام الٰہی کیاکرتے تھے (تصدیق براہین احمدیہ جلد ۱ صفحہ ۱۱۵)اوریہ معنی اوپر کے تمام معنوں سے اچھے ہیں اورزیاد ہ صحیح ہیں.کیونکہ اس سے پہلے اوراس آیت کے بعد بھی قرآن کریم کاہی ذکر ہے.حضرت مسیح موعود کے نزدیک اس جگہ روح سے مراد روح انسانی ہے مگرحضرت مسیح موعودؑ بانی سلسلہ احمدیہ نے نہایت وضاحت سے اس آیت پر بحث کی ہے.اوراس کے معنی انسانی روح ہی کے لئے ہیں.اور فرمایا ہے کہ اس آیت میں روح کے متعلق بہت بڑے معارف بیان کئے گئے ہیں (چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد ۲۳ صفحہ ۱۵۹).اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے.اس کے متعلق احادیث میں مختلف روایات آتی ہیں.بعض میں تولکھا ہے.کہ یہ سوال یہود نے مدینہ میں کیاتھا(ترمذی ابواب التفسیر باب سورۃ بنی اسرائیل).مگر اس کے خلاف یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے.اس کا جواب وہ لو گ یہ دیتے ہیں کہ اس سورۃ کی بعض آیتیں مدنی ہیں (مگر جیساکہ میں اوپر بیان کرآیا ہوں یہ درست نہیں ).بعض نے کہا ہے کہ یہ سوال پہلے مکہ میں ہواتھا.اورپھر دوبارہ مدینہ میں ہوا(مسند احمد مسند عبداللہ بن مسعودؓ و عبد اللہ بن عباسؓ)عبداللہ بن مسعودؓکی روایت ہے کہ یہ سوال مدینہ میں ہواتھا(ترمذی ابواب التفسیر باب سورۃ بنی اسرائیل).اورعجیب بات یہ ہے کہ وہی اس بات کے راوی ہیں.کہ یہ سورۃ مکی ہے(قرطبی).اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیاہے کہ یہی سوا ل دوبار ہ پھر مدینہ میں ہواہوگا.جولوگ اس کومکہ کی روایت قراردیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے بعض لوگ مدینہ گئے تھے.اوروہاں جاکر
Page 420
انہوں نے یہود سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ذکر کیا ورکہا کہ اس طر ح پر ایک مدعی نبوت ہم میں کھڑاہواہے ہم اس سے کیا سوال کریں.جس سے اس کاجھوٹ کھل جائے.انہوں نے جواب دیا کہ روح اوراصحاب کہف اورذوالقرنین کے متعلق اس سے سوال کرو.اس پر ان لو گوں نے مکہ میں واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا.اوریہ آیت نازل ہوئی (روح المعانی زیر آیت ھذا).یہ آیت مکی ہے میرے نزدیک پہلی دفعہ سوال مکہ میںہی ہواہے.اور وہیں اس کا جواب ملا ہے.ممکن ہے مدینہ میں بھی یہود نے سوال کیا ہو.بلکہ اغلب ہے کیونکہ جب یہود کی انگیخت سے یہ سوال ہوا تھا توانہوں نے بھی ضروریہ سوال کیا ہو گا.مگر یہ درست نہیں کہ دوبار ہ یہ آیت اتری.بلکہ جب مدینہ میں یہ سوال ہواہوگا.تورسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے یہ آیت جواب میں پڑھ دی ہوگی.اس واقعہ کو کسی راوی نے بیا ن کیا.اوربعد کے راویوں میں سے کسی نے سمجھ لیاکہ شائد اس سوال کے جواب میں یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی تھی.سوال کی حقیقت بیان کرنے کے بعد میں جواب کو لیتاہوں.مفسرین لکھتے ہیں.کہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوالوں کے جواب تواللہ تعالیٰ نے تفصیلاً دیئے.اوراس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ روح خداکے حکم سے ہوتی ہے.اور تم کواس بارہ میں بہت ناقص علم دیا گیا ہے.اس لئے تم اس کی حقیقت کونہیں سمجھ سکتے.اس لئے ہم تفصیل سے جواب نہیں دیتے اس پر یہود شرمندہ اورخاموش ہوگئے (روح المعانی زیر آیت ھذا).اس جواب پر آریہ مصنفین نے بہت اعتراض کئے ہیں.اورلکھاہے کہ اس جواب سے یہود کوشرمند ہ ہونے کی کیاضرورت تھی.کونسا مدلل و مسکت جواب دیا گیا تھا کہ وہ شرمند ہ ہوجاتے (کلیات آریہ مسافر تکذیب براہین احمدیہ صفحہ ۷ ).حضرت خلیفۃ المسیح اوّل کے نزدیک روح سے مراد جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں.استاذی المکر م حضرت مولوی نورالدین صاحب اس کے یہ معنی کرتے تھے.کہ روح سے مراد اس جگہ کلام الٰہی ہے.اورجواب یہ دیاگیاہے کہ کلام الٰہی حکم الہی سے نازل ہوتاہے.اوراس کی ضرورت یہ ہے کہ تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے.پس انسانی علم کے ناقص ہونے کی صورت میں ضروری تھاکہ اللہ تعالیٰ انسان کے علم کو روحانیت کے بارہ میں مکمل کرتا.سو اس ضرورت کے ماتحت اس نے اپنا کلام نازل کیاہے.جیسا کہ میں بحر محیط کے حوالہ سے اوپر لکھ آیاہو ں پر انے مفسروں میں سے بھی بعض نے روح سے قرآن کریم مراد لیا ہے (البحرالمحیط زیر آیت ھذا).اوران کی تفسیر حضرت استاذی المکرم کی تفسیر سے ملتی ہے.لیکن جیساکہ ظاہر ہے کہ روح سے صرف قرآ ن کریم مراد لینا اس قدر
Page 421
واضح نہیں جس قد رکہ کلام الہی کامراد لینا.اس لئے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت استاذ ی المکرم کاقول زیادہ واضح اورموقعہ کے مناسب ہے.حضرت مسیح موعود ؑ کے نزدیک الروح میں روح انسانی کی طرف اشارہ ہے میں ایک عرصہ تک انہی معنوں پر حصر کیاکرتاتھا.مگر جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ کی بعض تحریرات کو غو ر سے پڑھا.تومجھے اپنے خیا ل میں کچھ تبدیلی کر نی پڑی.اورتسلیم کرناپڑ ا کہ روح انسانی کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے.او ران معنوں سے آیت کامضمون بہت وسیع اوربہت لطیف ہو جاتا ہے.آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلق دوطرح کی ہے.(۱)ابتدائی خلق جو بغیر مادہ کے ہوتی ہے.(۲)بعد کی خلق جوپہلے سے پیداکئے ہوئے مادہ سے ہوتی ہے.جس خلق میں اللہ تعالیٰ دنیوی اسباب سے کام لیتا ہے.یعنی ایسے ذرائع کواستعمال کرتا ہے.جوکسی چیز کی پیدائش سے پہلے موجود ہوں.اس کانام خلق رکھا جاتا ہے.اورجس چیز کو اللہ تعالیٰ بغیر ان ذرائع کے جوپہلے سے موجود ہو ںپیداکرتاہے اس کانام امر رکھا جاتاہے.جس کی طرف کُنْ فَیَکُوْن کےا لفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں اسی قسم کی تخلیق کے متعلق جواب دیاگیا ہے.جواذن الہی سے ہوتی ہے.آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آریہ اس پر اعتراض کرےگااور میرے مقا بل آئے گا تومیں ایک رسالہ لکھوں گا جس میں بتائوں گاکہ قرآن کریم نے روح کے اندر کیاکیاقوتیں اورطاقتیں بیان فرمائی ہیں (سرمہ چشمہ آریہ روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۲۳۳).مگر افسوس کہ کوئی آریہ مقابل پر نہ آیا.اورہم اس قیمتی خزانہ سے محروم رہ گئے.جو ہم کومفت میں ملنے والاتھا.مگرپھر بھی آپ کی بعض کتب سے رہنما ئی حاصل کرکے ہم ایک کافی علم اس بار ہ میں حاصل کرتے ہیں.اورشاید اللہ تعالیٰ نے بقیہ علم کو کسی حکمت کے ماتحت کسی اورزمانہ کے لئے محفوظ رکھ چھوڑاہو.اب میں ان معنوں کی بناء پر جو بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام نے کئے ہیں.اس آیت کی تشریح اپنی سمجھ کے مطابق کرتاہوں.اورمجھے یقین ہے کہ جو شخص بھی تعصب سے خالی ہوکر ان معنو ں پرغورکرے گا.و ہ محسوس کرے گاکہ اس آیت میں یہود کے سوال کو بے جواب نہیں چھوڑاگیا بلکہ اس کانہایت لطیف اور مسکت جواب دیا گیا ہے.اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوجائے گاکہ جن لوگوں نے اس جگہ روح کے معنی کلام الہی کے کئے ہیں.یاقرآن کریم کے کئے ہیں.انہوں نے بھی غلطی نہیں کی.بلکہ صداقت ہی کو بیان کیاہے.بات یہ ہے کہ پہلی آیات میں قرآن کریم کی فضیلت اوراس کی ضرورت کوبیان کیاگیا تھا.بلکہ پہلی دوسورتوں میںتواسی مضمون پر سارازور تھا.سورۃ حجر اورسورۃ نحل جیسا کہ میں ثابت کرآیا ہوں.قرآن کریم کی طاقت اوراس کی
Page 422
قوت کے متعلق ہی دلائل بیا ن کرتی ہیں.اس سورۃ میں بھی یہی بیان کیاگیاہے کہ جب تک یہود کلام الہی سے وابستہ رہے ترقی کرتے رہے جب انہوں نے کلام الٰہی کو چھو ڑ دیا.توان پرعذاب نازل ہوا.یہود چونکہ اپنے خیال میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پر سبت کی بے حرمتی کی وجہ سے عذاب آیا ہے انہیں یہ مسئلہ عجیب معلوم ہوا بلکہ برابھی لگا.خصوصاً اس لئے کہ عیسائی لوگ مسیح کوکلمۃ اللہ کے نام سے موسوم کرتے تھے.پس یہ الفا ظ کہ خدائی کلام کے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب آیا.انہیں بہت دکھ دیتے تھے.جھوٹے تصوف کی طرف رجحان کلام الٰہی کے بند ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ادھر یہود میں ایک اورنقص بھی پیداہوگیاتھا.جو مایو س اقوا م میں عام طور پر پیداہو جایا کرتا ہے.اوروہ یہ کہ جب وہ کلام الہی سے محروم ہوگئے.اورنبوت کاسلسلہ ان میں بند ہوگیا.تووہ جھوٹے تصوف کی طرف راغب ہوگئے.اورخاص خاص مشقوں کے ذریعہ سے بزعم خود اپنی روحانی قوتوں کے بڑھانے میں مشغول ہوگئے.کوئی توذکر اذکار کے ذریعہ سے اپنی قوتوںکو بڑھاتا.اور کوئی اسم اعظم کوقابو میں لاکر اپنی روحانیت کو ترقی دیتاتھا.اوریہ سب لوگ خیال کرتے تھے کہ جو کمی وحی الٰہی کے نہ آنے سے پیداہوگئی تھی.وہ ا س طرح انہوں نے دور کرلی ہے.یہ مرض حضرت دائود کے زمانہ سے پیداہوئی اور حضرت مسیح کے نزول کے وقت تک بہت ترقی کرگئی.ان کاخیال تھا کہ ارواح کوقابو میں لاکر یااپنی روح کوجلادے کر انسان بہت بڑے بڑے معجزات دکھا سکتاہے.اورعلوم غیبیہ کوپاسکتا ہے.یہود کے نزدیک روح کی دو قسمیں اسم اعظم اور بعل سے متعلق اوروہ اس علم کو دوحصوں میں تقسیم کرتے تھے ایک جائز علم جسے وہ اسم اعظم سے وابستہ کرتے تھے.اورایک ناجائز جسے وہ بعل سے تعلق کا نتیجہ بتاتے تھے.چنانچہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا اورمعجزات دکھائے توانہوں نے ان کے معجزات کی یہی تشریح کی.کہ اس کابعل کے ساتھ تعلق ہے.چنانچہ اس کا ذکر انجیل میں ان لفاظ میں آتاہے.’’فقیہہ جو یروشلم سے آئے تھے یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ بعلز بول ہے.اوریہ بھی کہ وہ بدروحوں کے سردارکی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے.وہ انہیں پاس بلاکر تمثیلوں میں ان سے کہنے لگا.شیطان کو شیطان کس طرح نکال سکتا ہے.‘‘(مرقس باب ۳آیت ۲۲.۲۳) (یہی ذکر متی باب ۹آیت ۳۴و باب۱۰.۲۵.لوقاباب ۱۱.۱۵ اوریوحنا باب ۷.۲۰ اورباب ۸.۴۸.۵۲ وباب ۱۰.۲۰میں بھی آتاہے )بعل زبویا بعل زبول یابعل زبوب درحقیقت ایک ہمسایہ قوم کادیوتا تھا.چونکہ اس کی نسبت لوگوں میں معجزات مشہور تھے.یہو د میں جب جادوکاخیال پیداہواتووہ اس کے متعلق یہ خیال
Page 423
کرنے لگے کہ یہ بعل سفلی دنیا کاسردار ہے.اوراس سے تعلق پیداکرکے کفار لوگ معجزات دکھاتے ہیں.(انجیل کے مذکورہ بالا حوالہ جات نیز انسائیکلو پیڈیا ببلیکا نیز جوئش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ بیل زبو ل Beelzebul)اس کے برخلاف جو روحانی طاقتیں بزعم خود و ہ آپ حاصل کرتے تھے انہیں اسم اعظم کا نتیجہ بتاتے تھے.اوراس جادوکو جائز جادو سمجھتے تھے.جوئش انسائیکلوپیڈیا میں لکھاہے.کہ مسیح سے کم سے کم تین سوسال پہلے سے اسم اعظم کارواج یہود میں پایا جاتاہے.اسم اعظم کی طرف توجہ حضرت داؤد کے زمانہ سے ہوئی ( میں بتاچکا ہوں کہ میری تحقیق میں حضرت دائود کے زمانہ سے ان میں یہ خیال پیداہوچکاتھا.حضرت سلیمان کے زمانہ میں اورترقی کرگیا ).و ہ اسم اعظم کی نسبت یہ مشہورکرتے تھے.کہ وہ نہ بولاجاسکنے والانام ہے (جوئش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Names of God ) یہود میں جوجادوگر تھے.وہ اس کانام خاص طور پر اشاروں میں لکھتے تھے.یہ لوگ خصوصاً مصر میں پائے جاتے تھے.(حوالہ متذکرہ بالا) سیاہ جادو اور سفید جادو کی تشریح یہود کاخیال تھا کہ سیاہ جادواورسفید جادودونوں حق ہیں.سیاہ جادو شیطانوں سے تعلق کی وجہ سے حاصل ہوتاہے.اورسفید جادواسماء الٰہی سے تعلق کی وجہ سے.سیاہ جادومنع ہے.اورسفید جادو جائز ہے.لکھا ہے کہ علماء یہود سیاہ جادو کے مخالف تھے.مگر سیا ہ جادوکامقابلہ کرنے کے لئے وہ سفید جادو کے استعمال میں ہرج نہ دیکھتے تھے.علماء یہود میں(بقول ان کے)اس جادو کے ذریعہ سے اس قدر طاقت پیداہوجاتی تھی.کہ وہ ایک نظر ڈال کر دشمن کو بھسم کردیتے تھے.یااسے ہڈیوں کاایک ڈھانچہ بنادیتے تھے.بیماروں کواچھا کرتے تھے.ان امورکاان میںاس قدر رواج تھا کہ یونانی اوررومی لوگ یہود کوجادوگرکہاکرتے تھے.(جوئش انسائیکلوپیڈیا زیرلفظ میجک یعنی جادو جلد ۸) اس کے علاوہ یہود کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ مردہ ارواح سے تعلق پیداکرکے غیب کے علوم معلوم کئے جاسکتے ہیں.چنانچہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے اوراس سے منع کیاگیا ہے.استثناء باب ۱۸.۱۱میں بھی ا س کا ذکر آتاہے.اوراوربہت سی آیات میں بھی.اسی طرح یسعیا ہ باب ۸.۱۹میں بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جوارواح سے تعلق پید اکرکے غیب کاحال معلوم کرتے تھے.اوران سے تعلق پیداکرنامنع کیا گیا ہے.یسعیاہ کہتے ہیں کہ جب لوگ تجھے ایسے لوگوں سے تعلق پیداکرنے کو کہیں توان سے کہہ کہ’’کیازندوں کی نسبت مردوں سے سوال کریں ‘‘.جوئش انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہے بنی اسرائیل نے غالباًیہ فن ایرانیوں سے سیکھاتھا.اوران میں کثر ت سے اس
Page 424
کارواج پایاجاتاتھا.(جلد ۹زیر لفظ نیکرومنسی یعنی علم الارواح Necromancy)خلاصہ یہ کہ یہود کاعقیدہ تھا کہ ارواح سے تعلق پیداکرکے غیب کے علوم دریافت کئے جاسکتے ہیں.اورگوان کواس سے منع کیا گیا تھا.مگر پھر بھی وہ کثرت سے ا س علم کوسیکھتے اوراس پر عمل کرتے تھے.موجودہ زمانہ میں بھی اس کابہت رواج ہے.یورپ میں اس علم والوں کو سپر چولسٹ کہتے ہیں.یعنی روحانیین تھیا سوفیکل سوسائٹی کی بنا ہی اس علم پر ہے.موجودہ تھیاسوفی کی بانی مسز اینی بسنٹ کایہ عقید ہ تھا.کہ ارواح سے وہ بہت کچھ سیکھتی ہیں.اوروہ اس کے ماتحت غیب کی خبریں بھی بتاتی تھیں.چنانچہ بزعم خود انہوں نے ا س علم سے کام لے کر ایک بڑے اوتار کے آنے کی خبر دی تھی.جس کی نسبت ان کاخیال تھا کہ کرشنا مورتی اس کامصداق ہے(انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس زیر لفظ Theosophy).ا ب یہ نوجوان جوتعلیم دیتاہے.وہ قریباًدہریت کی تعلیم ہے.گزشتہ جنگ یورپ میں جب بہت سے گھرانوں کے نوجوان مارے گئے.اس کی طرف خاص توجہ ہوگئی.اورسرکینن ڈائل مشہور مصنف نے اپنی آخری عمراپنے ایک لڑکے کی یاد میں اس علم میں گزاردی.مشہور ادیب اورسیاستدان ڈبلیو ٹی سٹڈ بھی اسی خیال کے تھے.اورانہوں نے اپنے تجربوں کی کتاب بھی شائع کی ہے.مشہور سائنسدا ن سرآلیورلاج بھی آخری عمر میں اس عقید ہ کے ہوگئے تھے.کہ ارواح سے تعلق پیدا کیاجاسکتاہے اورانہوں نے بھی کئی کتب اس بار ہ میںلکھی ہیں(کینن ڈائل صفحہ ۱۴۰.۱۵۰ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ لاج Lodge).ہندوؤں کا یوگا علم الارواح ہندوئوں میں یوگاکے نام سے یہ علم رائج ہے.اوران کے ایک شاسترمیں جسے پتنجلی کایوگ شاستر کہتے ہیں اس مضمو ن پرخاص بحث کی گئی ہے (انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس زیر لفظ یوگا Yoga).مسلمان صوفیاء نے بھی تنز ل کے زمانہ میں اس علم کی طرف توجہ کی.اورعلم اشراق اورحاضرات وغیرہ کے نام سے بہت کچھ رطب و یابس اس پر لکھاہے اورکہاہے اوراس نام نہاد علم کو استعمال کیاہے (التبیان فی مسائل السلوک والاحسان المعروف بدلائل السلوک صفحہ ۱۵۱.۱۶۹).خلاصہ یہ کہ علم الارواح ایک قدیم علم ہے.اوریہود میں اس کاخاص رواج تھا.خصوصاً جب ان کاتعلق دین سے کم ہوااورالہام کادروازہ بند ہواتووہ اس کی طرف بہت متوجہ ہوگئے.حضرت مسیح ناصر ی کے وقت میں ان میں اس کا رواج بہت بڑھا ہوا تھا.چنانچہ حضرت مسیح کے وقت میں ایک فرقہ یہود کا اسینیوں کے نام سے تھا.جن کی نسبت انجیل میں فریسیوںکے لفظ سے اشارہ کیاگیاہے.
Page 425
یہود کے فرقہ اسینیوں کے حالات بعض لوگوں کاخیال ہے کہ حضرت مسیح اسی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ ایک پرانانسخہ کتاب کا جرمنی میں ملا ہے.جس میں ایک اسینی نے دعویٰ کیا ہے کہ مسیح ہمارے فرقہ کے ایک آدمی تھے.اور مسیح کی زندگی کے حالات عجیب پیرایہ میں اس میں لکھے ہیں.اوریہ بھی لکھا ہے کہ و ہ صلیب پر سے زندہ اترآئے تھے.دیکھو THE CRUCIFIXION BY AN EYE WITNESS یہ کتاب میرے کتب خانہ میں موجود ہے.اس فرقہ کی نسبت انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں لکھا ہے.کہ یہ لو گ روزے رکھتے.اوربڑی پا ک زندگی بسرکرتے تھے.اورغیب کی خبریں بتاتے تھے.اورمعجز ے دکھاتے تھے.چنانچہ فائلو philo ان کی نسبت لکھتاہے.کہ غیر قوموں کے جادوگروں سے مرعوب نہ ہوناچاہیے.ہمارے اند ر بھی ایسے لوگ موجود ہیں اورا س نے مثال کے طور پر اسینیوں کو پیش کیا ہے.جوزیفس مشہور یہودی مصنف بھی ان کے ذکر میں لکھتاہے کہ وہ پیشگوئیاں کرتے تھے.اورغیب کی خبریں بتاتے تھے ان کی نسبت لکھا ہے کہ عبادت کے وقت مراقبہ کرتے تھے.تاان کی ارواح کاتعلق آسمانی باپ سے پیداہوجائے اوران کے لیڈر اسم اعظم کے جاننے کادعویٰ کرتے تھے جوبقول ان کے بیالیس حرفوں کاہے.یہ لوگ عورتوں سے الگ رہنے کو پسند کرتے تھے.تاکہ ’’مزید الہام ان پر نازل ہو‘‘.(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Essenes) ایسامعلوم ہوتاہے کہ مدینہ کے یہود اسی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے.عبد اللہ بن صیاد ارواح سے تعلق کی وجہ سے غیب کا دعویدار تھا کیونکہ حدیث میں آتاہے کہ مدینہ کے یہود میں سے ایک شخص عبداللہ بن صیاد پیشگوئیاں کیاکرتاتھا جب اس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی توآپ ا س کاامتحان کرنے کے لئے گئے.اور چونکہ وہ غیب کے علم کادعویٰ کرتا تھا.آپ نے اس سے پوچھا.کہ میں نے اپنے ذہن میں ایک لفظ رکھا ہے.تم بتائو کہ وہ کیاہے.آپ نے سورہ دخان کی آیت فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ(الدخان:۱۱)ذہن میں رکھی تھی.اس نے سوچ کرجواب دیا.دُخْ.دُخْ اورآگے خاموش ہوگیا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.لَنْ تَعْدُ وَ قَدْرَکَ توجس حیثیت کاہے.اس سے آگے نہ بڑھے گا.یعنی تیراعلم دماغی ہے.توالٰہی اخبار کونہیں بتاسکتا.اس شخص کے متعلق صحابہ کوخیال تھا کہ یہ دجال ہے.چنانچہ حضرت عمر ؓ نے اسے قتل کرنے کااراد ہ کیا.مگررسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے آپ کو یہ کہہ کرمنع فرمایا.کہ اگریہ دجال ہے توتم اس کومار نہیں سکتے.اوراگریہ دجال نہیں تواس کامارناناجائزہے (مسلم کتاب الفتن باب ذکر ابن صیاد).بہرحال اس واقعہ سے معلو م ہوتاہے کہ مدینہ کے یہود میں اس قسم کے لوگ موجود تھے.جوارواح سے تعلق رکھنے کے مدعی تھے.اوریہ اس امر کاثبوت ہے کہ وہ اسینی فرقہ کے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے.
Page 426
کفار کے آنحضرت ؐ سے روح کے متعلق سوال کرنے کی وجہ اس تمہید کے بعد میں یہ بتاناچاہتاہوں کہ جب قرآن کریم نے غیب کی خبریں بتائیں.اورکفار نے جواب سے عاجز آکر یہود سے اس بار ہ میں مدد چاہی توانہوں نے ان سے کہا کہ اس شخص سے روح کے متعلق سوال کرویعنی روح میں کیاکیا قوتیں ہیں.اس سوال کے جواب سے وہ پکڑاجائے گا.ان کاخیال تھاکہ اگر توآپ یہ جواب دیں گے.کہ روح میں بڑی بڑی طاقتیں ہیں.جن سے وہ علم غیب معلوم کرلیتی ہے.توہم کہیں گے کہ پھر قرآنی علوم کو ہم خدا تعالیٰ کی طر ف سے کیوں سمجھیں.کیوںنہ اسے آپ کی بعض روحانی مشقوں کانتیجہ قرار دیں.اوراگر آپ یہ جواب دیں گے کہ روح میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے.توہم آپ کے اس جواب پر آپ کی جہالت کوثابت کریں گے.گویا ان کے نزدیک قرآنی علوم محض ایک دماغی مشق کانتیجہ تھے.اس امر کاثبوت کہ یہود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ میں ارواح سے تعلق پیداکرنے کا خیال پایاجاتاتھا.قرآن کریم سے بھی ملتا ہے.چنانچہ سورئہ جن میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کرکے جوموسیٰ پر ایمان لائی تھی اورجن کی نسبت میں پہلے ثابت کر آیا ہوں.کہ وہ انسان ہی تھے.ان کایہ قول نقل فرمایا ہے.اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ( الجن :۱۰)کہ ہم آسمانی خبروں کومعلوم کرنے کے لئے آسمان کی طرف توجہ کرکے بیٹھاکرتے تھے.یعنی مراقبہ کیاکرتے تھے.اگریہود ایساسوال نہ کرتے تب بھی قرآن کریم میں اس سوال پر روشنی ڈالنی ضرو ری تھی.کیونکہ یہ عقیدہ درحقیقت سب سچے مذہبوں پرحملہ ہے.اوراس سے یہ ظاہرہوتاہے کہ خدا تعالیٰ کے بتائے بغیر بھی انسان ارواح کی مدد سے ہدایت کے اصول دریافت کرسکتاہے.جیساکہ تھیاسوفی والے ظاہر کرتے تھے.اوراس عقیدہ کے روسے ہرشخص جو بعض نام نہاد روحانی مشقیں کرے.علوم غیبیہ سے آگاہ ہوسکتا ہے.ظاہر ہے کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہو تومذہب کے بارہ میں امن بالکل اٹھ جاتا ہے.روح کے امر ربی ہونے کی تشریح قرآن کریم اس سوال کا جواب یہ دیتا ہے کہ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ.اے محمد! رسول اللہ توان سے کہہ دے کہ روح کامل یعنی جوروح خدا تعالیٰ سے صحیح تعلق رکھتی ہے اوربعض علوم غیبیہ سے آگاہ کی جاتی ہے مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیارہوتی ہے.بغیر امر رب کے کوئی روح کامل نہیں ہوسکتی.اورجس قسم کی مشقوںا ورجادوئوںاور یوگاکوتم روح کے کامل کرنے کاذریعہ بتاتے ہو.یہ بالکل غلط خیا ل ہے.روح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کامل ہوتی ہے گویا اس جگہ الروح سے مراد کامل روح ہے جوسب
Page 427
روحانی صفات کو اپنے اندررکھتی ہو.جیسے کہ قرآن کریم کے شروع میں ہی آتاہے.اَلْحَمْدُلِلہِ کامل حمد جس میں حمد کی سب ضروری صفا ت پائی جائیں اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے.انہی معنوں میں الروح کا لفظ اس جگہ استعمال ہواہے.اوریہ بتایاگیا ہے کہ روح کوکامل کرنے کاکا م اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھاہے.بغیراذن الہی کے کوئی روح کامل نہیں ہوسکتی.خواہ اس کے کامل کرنے کے لئے کتنے ہی یوگ استعمال کئے جائیں.اورکتنی ہی مشقیں کی جائیں.اس دعوےٰ کی ایک تازہ مثال کرشنا مورتی کاوجود ہے.مسز اینی بیسنٹ نے اس نوجوان کو اوران کے ایک اوربھائی کو خاص طور پر یوگا کے اصول کے ماتحت پالاتھا.اوربڑے بڑے ماہر فن ان کی تربیت پرمقر ر کئے تھے.کہ روزانہ توجہ سے ان کے خیالات کودرست رکھیں.لیکن نتیجہ یہ ہواکہ جو بڑابھائی تھا وہ تو ہروقت شکایت کرتاتھا کہ ہم قید یوں کی طرح ہیں.اورخوامخواہ ہم پرجبر کیا جاتا ہے.اورچھوٹابھائی جسے بڑے کی بغاوت کی وجہ سے چنا گیا.اب علی الاعلان مسزاینی بیسنٹ کے خیالات کی تردید کررہاہے (انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ کرشنامورتی Krishana murti).اگرکہا جائے کہ قرآن کریم کایہ جواب تو ایک دعویٰ ہے جواب کہلانے کامستحق نہیں.تواس کا جواب یہ ہے کہ اس حد تک توصرف اصل بتایاگیاہے.سوال کا جواب آیت کے اگلے حصہ سے شروع ہوتا ہے وَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا کہہ کر یہ ظاہر کیاگیا ہے.کہ روح کی قوتوںکو نشوونمادینے کےلئے جو مشقیں انسانوں نے بنائی ہیں گوان کے نتیجہ میں بعض قوتیں روح کو حاصل ہوجاتی ہیں.مگرو ہ حقیقی قوتوں کے مقابلہ میں بالکل ناقص اورتھوڑی ہیں.پس ان کی بناء پر کلام الٰہی کاانکار عقل کے خلاف ہے.ناقص شے کامل کی قائم مقام کسی صورت میں نہیں ہوسکتی.علم الارواح کے ناقص ہونے کاثبوت اس سے حاصل شدہ خبروں میں شدید اختلاف اس امر کاثبوت کہ یہ علم بالکل ناقص ہے میں ہمیشہ یہ دیاکرتاہوں.کہ مختلف مذاہب کے لوگ جواس علم کی مدد سے روحانی باتیں دریافت کرتے ہیں.ان کی معلوم ہوئی خبروں میں شدید اختلاف پایا جاتاہے.اگرروحانی مشقوں سے سابق ارواح سے حقیقی طور پر علوم دریافت کئے جاسکتے.تویہ اختلاف کبھی نہ ہوتا.بھلایہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح ایک ہندویوگی کو کچھ اوربتاجاتی ہے.اورایک مسیحی روحانی کوکچھ اوربتاجاتی ہے.اورایک یہودی کو کچھ اوربتاجاتی ہے.جولوگ اس علم کے ماہر ہیں.ان میں سے ایک صاحب مسٹر انکسنس امریکن جو بہت سی کتب کے مصنف ہیں
Page 428
صاف لکھتے ہیں کہ ہم کو بری اورمنذرباتوں کاعلم ہو جاتا ہے.اورآئندہ کی اچھی خبریں نہیں ملتیں.یہ گویا اپنے مونہہ سے اقرار ہے کہ وَ مَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.حالانکہ انبیاء کی نسبت قرآ ن شریف یہ فرماتا ہے.وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ (الکہف:۵۷) رسولوں کاپہلاکام وہ اخبارغیبیہ بتاناہے.جوبشارتوں پر مشتمل ہوتی ہیں اوردوسراکام انذاری خبروںکابتانا ہے.وَ لَىِٕنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا اوراگر ہم چاہیں تویقیناً جو(کلام الٰہی )ہم نے تجھ پر وحی (کے ذریعہ سے نازل )کیاہے.اسے (دنیاسے )اٹھالیں تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًاۙ۰۰۸۷ پھر تواس امر میں اپنے لئے ہمارے خلاف کوئی کارساز نہیں پاسکے گا.تفسیر.اس آیت میں گوخطاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے ہے.مگرمراد انسان ہے.کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کانہ توکوئی اعتراض تھانہ سوال.جن کاسوال تھاانہی کو جواب دیاگیاہے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب صرف مضمون پرزوردینے کے لئے ہے.فرماتا ہے کہ روح بغیر امر الٰہی کے ایسی ناقص شے ہے.کہ علوم روحانیہ کابراہ راست لے آناتوبڑی بات ہے جوعلوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوچکے ہیں.وہ اگر مٹ جائیں توان کو بھی روحانی لوگ واپس نہیں لا سکتے خواہ کتنے لوگ مل کرکوشش کریں.مثلاً قرآن کریم ہی ہے اس کے علوم کو اگر ہم مخفی کردیں.توکوئی ان علوم کوواپس نہیں لاسکتا.شائدکوئی کہے کہ یہ ایک دعویٰ ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہیں بلکہ زبردست ثبوت ہے کیونکہ قرآن کریم آسمان پر توجائے گانہیں.مگر جن کے دماغوں میں قرآنی برکات نہیں ان کے لئے ان کے لئے قرآنی علوم ویسے ہی ہیں جیسے کہ دنیا سے چلے گئے.وہ لوگ اگر چاہیں.کہ قرآنی تعلیم جیسی کوئی تعلیم پیش کردیں.تووہ ایسانہیں کرسکتے.چنانچہ اگلی ہی آیت میں ا س شبہ کابھی ازالہ کردیاگیاہے.قرآن کریم کی حقیقت کے مٹنے کی پیشگوئی اس آیت میں اس طرف بھی اشار ہ کیاگیاہے.کہ قرآن کریم زمین سے اٹھ جائےگا.اوراحادیث میں بھی یہ ذکرآتاہے.ابن مسعود اورابن عمرسے ابن مردویہ نے روایت کی
Page 429
ہے کہ قرآن کریم دنیاسے اٹھ جائے گا.اورصرف لَااِلٰہَ اِلَّااللہُ رہ جائے گا.اسی طرح بیہقی اورابن ماجہ نے حذیفہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اورقرآن دنیاسے اٹھ جائیں گے (ابن ماجہ کتاب الفتن باب ذھاب القرآن والعلم ،شعب الایمان للبہیقی باب فی نشر العلم).ان رویات سے معلوم ہوتاہے کہ اس آیت میں ایک پیشگوئی بھی کی گئی ہے.اوربتایا گیا ہے کہ ایک وقت میں صرف قرآن کریم کے الفاظ رہ جائیں گے.مگر حقیقت مٹ جائے گی.اورجھوٹے صوفی جوارواح سے تعلقات کے دعوے کرتے ہیں قرآن کے معارف کوواپس نہ لاسکیں گے.میراہمیشہ یہ طریق ہے کہ ان جھوٹے صوفیوں کے بارہ میں یہ کہاکرتا ہوں کہ قرآن کریم کی مشکل آیات میں ان کے سامنے رکھتا ہوں وہ اپنی ارواح سے ان کے مطالب حل کرکے ہمیں بتادیں.اگر قرآنی علوم انہوں نے معلوم کرلئے توسچے ورنہ جھوٹے.مگریہ کام نہ آج تک کوئی کرسکانہ کرسکتاہے.اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ١ؕ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا۰۰۸۸ اپنے رب کی (خاص )رحمت کے سوا(کہ وہی اسے واپس لاسکتی ہے.مگریہ قرآن مٹ نہیں سکتاکیونکہ )تجھ پرتیرے ر ب کایقیناً(بہت )بڑافضل ہے تفسیر.تیرے رب کافضل تجھ پر بڑاہے.جب قرآن کریم دنیاسے اٹھ جائے گا.توپھر تیرارب ہی اس کو لائے گا.اس سے مراد یہ ہے.کہ اس کی مثل لاناتو الگ رہا اس کے علوم کے مخفی ہونے پر کوئی شخص بغیر الٰہی مددکے ان کوظاہر بھی نہیں کرسکتا.قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ تو(انہیں )کہہ(کہ )اگر تمام انسان(بھی)اورجن (بھی اس کی نظیر لانے کے لئے )جمع ہوجائیں.هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ تو(پھر بھی)وہ اس کی مثل نہیں لاسکیں گے.خواہ وہ ایک د وسرے کے لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا۰۰۸۹
Page 430
مددگار (ہی کیوں نہ)بن جائیں.حل لغات.ظھیر.ظَھِیْرٌ ظَھَرَسے صفت مشبہ ہے.اورظَھَرَ عَلَیَّ کے معنی ہیں.اَعَانَـنِیْ اس نے میری مددکی.ظَھَرَ فُلَانًا بِفُلَانٍ وَعَلَیْہِ :غَلَبَہُ.اس پر غالب آیا.ظَھَرَبِزَیْدٍ:أَعْلَی بِہٖ وَرَفَعَ مَرْتَبَتَہُ.زیدکو ترقی دی اوراس کامرتبہ بلندکیا.اَلظَّھِیْرُ الْمُعِیْنُ مدگار معاو ن(اقرب) تفسیر.قرآن کی مثل لانےسے عجز دعویٰ کی سچائی کا ثبوت ہے اس آیت سے روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ جومعنی میں نے اوپر کی آیات کے کئے تھے وہی صحیح ہیں.کیونکہ ا س میں آکر اسی دلیل کو جو میں نے اوپر دی تھی مکمل کیاگیاہے.فرماتا ہے کہ تم کہتے ہوکہ بعض روحانی مشقوں سے ترقی کرکے انسان سابق ارواح سے روحانی تعلیمات حاصل کرسکتاہے.اگر تمہارایہ دعویٰ سچا ہے تواے انسانو تم سب کے سب اکٹھے ہوجائو.اوران مخفی ارواح کوبھی اپنی مدد کے لئے بلالو.جن کی نسبت تمہاراخیال ہے کہ تم کو علوم آسمانی سے خبردار کرتی ہیں.اورسب مل کرقرآن کی مثل کوئی کتاب پیش کردو.اوراگر تم نے اس کی مثل پیش کردی.تب توبے شک تمہارادعویٰ سچاہوگا.ورنہ صاف ظاہر ہے کہ تم اس دعویٰ میں جھو ٹے ہو.جب تم سب کے سب مل کر اور تمہاری ساری مخفی ہستیا ں مل کر بھی قرآن کی مثل نہیں لاسکتیں.تویہ کہنا کہ محمد رسول اللہ نے بعض روحانی مشقوں سے ان علوم کوحاصل کرلیا ہے.کتناجھوٹادعویٰ ہے.اس آیت میں جن سے مراد ارواح ہیں الْجِنُّ سے ا س جگہ مراد وہ ارواح ہیں جن کی مدد سے علوم روحانی سیکھنے کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں.چونکہ وہ ارواح بقول ان کے نظروں سے غائب ہیں.ان کو جنات کے نام سے اس جگہ یاد کیاگیا ہے.وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ١ٞ اورہم نے اس قرآن میں یقیناً ہرایک(ضروری)بات کومختلف پیرایوں سے بیان کیا ہے.پھر(بھی)اکثر لوگوں فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا۰۰۹۰ نے (اس کے متعلق ) کفر (کی راہ اختیار کرنے)کے سواہر بات سے انکار کردیاہے تفسیر.فرمایا یہ لوگ مثال لائیں گے کہاں سے.ان کے دماغ محدود ہیں.جس قسم کی یہ تربیت پائیں گے.اسی قسم کی بات پیش کرسکیں گے اورباقی باتیں ان سے رہ جائیں گی.لیکن اس قرآن کریم میں سیاسیات کے
Page 431
متعلق سائنس کے متعلق.اخلاق تمدن اوراقتصادیات کے متعلق سیر کن بحثیں ہیں.پھر مختلف مذاہب کے اختلافات کافیصلہ کیاگیاہے.ان کوتو ان باتوں کے سمجھنے کی بھی قابلیت نہیں یہ مثل کس طرح لا سکتے ہیں.ہاں اپنی ضد کی وجہ سے انکار کرناخوب جانتے ہیں.سومختلف بہانے اوراعتراض بنا بنا کر انکار کرتے چلے جائیں.آخر ایک دن نتیجہ بھگتنا پڑےگا.وَ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ اورانہوں نے(یہ بھی )کہا ہے (کہ )ہم ہرگز تیری(کوئی )بات نہیں مانیں گے.جب تک (ایسانہ ہو کہ ) يَنْۢبُوْعًاۙ۰۰۹۱اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ عِنَبٍ توہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے یاتیراکھجوروں اورانگوروں کاکوئی باغ ہو اورتواس کے اندر خوب فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًاۙ۰۰۹۲ (کثرت سے )نہریں جاری کرے.حلّ لُغَات.تفجّر.تُفَجِّرُفَـجَّرَ سے مضارع واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے.اس کاماد ہ فَـجَرَ ہے.فَـجَرَالْمَاء کے معنی ہیں بَـجَسَہُ وَفَتَحَ لَہُ طَرِیْقًا فَجَرٰی.پانی کوکھود کرنکالا.اوراس کے بہنے کے لئے راستہ بنایا.فَـجَّرَ میں عربی زبان کے قاعد ہ کے مطابق ان معنوں میں تشدید کے ساتھ زیادہ زور پیداہوگیا.(اقرب) ینبوعًایَنْبُوْعًاکے معنی ہیں عَیْنُ الْمَاءِ پانی کاچشمہ ہے.الْـجَدْوَلُ الکْثِیْرُ الْمَاءِ بہت پانی والی نہر.اس کی جمع یَنَابِـعُ آتی ہے (اقرب) تفسیر.جب یہود کے بتائے ہوئے اعترا ض کاایسادندان شکن جواب دیاگیا.توا ب انہوں نے پہلوبدلا.اوریہ اعتراض کیا.کہ اچھا قرآن میں ہرعلم موجود ہے؟اگرایساہے توزمین میں چشمہ پھوڑ کردکھائو یاباغ اگاکر دکھائو جس میں نہریں چلتی ہوں.اپنی طرف سے کفار نے یہ بہت بڑااعتراض سوچا.حالانکہ یہ اعتراض اعتراض کرنے والے کی عقل کی کوتاہی کاثبوت ہے.اس اعتراض کی وجہ جیساکہ میں اوپر بتاآیا ہوں.یہود اور دوسرے جاہل لوگوں کایہ خیال تھا.کہ ارواح سے تعلق رکھنے والے یا اسم اعظم جاننے والے جادویااسم کے
Page 432
زورسے جوچاہیں کرسکتے ہیں.اس زمانہ میں بھی بعض علماء نے یہ طریق اختیار کررکھاتھا.کہ بانی سلسلہ احمدیہ کے پاس آدمی بھجواتے کہ جاکر دوچار لاکھ روپے مانگو.اورجب و ہ انکار کریں توکہنا کہ مسیح کی نسبت آتا ہے کہ دولت لٹائیں گے.آ پ کادعویٰ بھی مسیح ہونے کاہے.کیاآپ چندلاکھ روپیہ بھی نہیں دے سکتے.اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ یاجیساکہ تیرادعویٰ ہے توہم پرآسمان کے ٹکڑے گرائے یااللہ (تعالیٰ)اورفرشتوں کو (ہمارے ) بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ قَبِيْلًاۙ۰۰۹۳ آمنے سامنے لاکھڑاکرے.حلّ لُغَات.کِسَفًا یہ کِسْفۃٌ کی جمع ہے.ا س کے معنے ہیں.اَلْقِطْعَۃُ مِنَ الشَّیْءِ.کسی چیز کا ٹکڑا.(اقرب) قبیلا اَلْقَبِیْلُ کے معنی ہیں اَلْجَمَاعَۃُ مِنَ الثَّلَاثَۃِ فَصَاعِدًا تین یاتین سے زیادہ آدمیوں کی جماعت اور رَأَیْتُہُ قَبِیْلًا کے معنے ہیں رَأَیْتُہُ عِیَانًا وَمُقَابَلَۃً کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے آمنے سامنے دیکھا (اقرب) تفسیر.یعنی انعامات نہیں لا سکتے چلوعذاب ہی سہی.آسمان ہم پرگرادو ،خدااورفرشتوں کوسامنے لائو کہ آکر ہمیں تباہ کردیں.کفار کے مطالبات مندرجہ آیت بطور تمسخر ہیں استاذی المکرم حضرت خلیفہ اولؓ فرمایاکرتے تھے کہ یہ وعدے قرآن کریم میں موجود ہیں اس لئے وہ ان کامطالبہ کرتے ہیں مگرمیرے نزدیک وہ مطالبہ نہیں کرتے بلکہ تمسخر کے رنگ میں یہ باتیں پیش کرتے ہیں.کیونکہ ان معنوں میں سے اکثر مدنی سورتوں میں بیان ہوئے ہیں اوریہ مکی سور ۃ ہے.دراصل کفار تمسخر کے رنگ میں کہتے ہیں کہ جب سب کچھ قرآن میں موجود ہے تواس کے زور سے چشمے چھوڑدو اورباغ لگائویا عذاب ہی لائو.کیونکہ ان کے ذہن میں یہ وہم سمایاہواتھا کہ جادواورکلام کے زورسے ان باتوں کو پیدا کیاجاسکتاہے.یہود کابھی یہی خیال تھا جیساکہ پہلے لکھا جاچکاہے.
Page 433
اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ١ؕ وَ یاتیراسونے کاکوئی گھر ہو.یاتوآسمان پر چڑھ جائے.اور ہم تیرے (آسمان پر )چڑھ جانے پر بھی نہیں مانیں گے لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ١ؕ جب تک کہ تو(اوپر جاکر)ہم پر کوئی کتاب (نہ )اتارے.جسے ہم (خود )پڑھیں.تو(انہیں )کہہ(کہ) قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًاؒ۰۰۹۴ میرارب (ایسی بے ہودہ باتوں کے اختیار کرنے سے )پاک ہے میں (تو)صرف بشر رسول ہو ں.حلّ لُغَات.الزخرف اَلزُّخْرُفُ: اَلذَّھْبُ سونا کَمَالُ حُسْنِ الشَّیْءِ انتہائی خوبصورتی (اقرب) ترقیٰ.تَرْقٰی رَقِیَ سے مضارع واحد مذکر مخاطب ہے رَقِیَ کے معنے ہیں.صَعِدَ اوپر چڑھا مصدر رَقْیٌ اوررُقِیٌّ آتاہے لیکن رُقِیٌّ.یَرْقِیْ کامصد ربھی ہے.جس کے معنے منتراورجھاڑ پھونک کرناہے (اقرب) تفسیر.یعنی ہم کوکچھ نہیں دیتے چلو اپنے لئے ہی کچھ کرو.فرعون نے بھی کہاتھاکہ موسیٰ کے ہاتوں میں سونے کے کڑے نہیںہیںاس لئے سچا نہیں.انہوں نے ترقی کرکے کہہ دیا کہ سونے کاگھر ہوتب سچا ہو سکتا ہے.اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ١ؕ وَ لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ اس میں انہوں نے معراج کے واقعہ پر اعتراض کیا ہے کہ اس قسم کاقصہ نہ سنادینا ہم توتب مانیں گے کہ توآسمان پر چڑھ جائے اورتووہیںرہے اورکتاب ہماری طرف پھینک دے تاکہ ہمیں تسلی ہوجائے کہ توواقعہ میں آسمان پرچڑھا ہے فرماتا ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا.توان کوجواب دے کہ میرارب اس قسم کے تماشوں اورلغو باتوں سے پاک ہے.خدا کاکلام جس طرح رسولوں پر نازل ہوتارہا ہے اسی طرح مجھ پرنازل ہوتارہاہے.اورجومعاملہ رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی میرے ساتھ بھی کرے گا.مگر جن باتوں کاتم مطالبہ کرتے ہو وہ اس کی شان کے بھی خلاف ہیں اورمیری رسالت اوربشریت کے بھی خلاف ہیں دوسرے اس کے یہ معنے ہیں کہ جوباتیں تم پیش کرتے ہو.ان میں سے
Page 434
بعض توتماشے کے طورپرہیں جو خدا کی شان کے خلاف ہیں.اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ توروحانیت کی ترقی کے لئے کلام نازل کرتا ہے اوربعض باتیں بشریت اوررسالت کے خلاف ہیں مثلاً آسمان پرجانا اوروہاں سے کتاب کاپھینکنا.باوجود اس آیت کے مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰؑ آسمان پر ہیں.حالانکہ وہ بشر رسول تھے نہ کہ ملائکہ میں سے.وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلَّاۤ اوران لوگوںکوجو ان کے پاس ہدایت پہنچی ایمان لانے سے صرف اس بات نے روکاکہ انہوں نے(اپنے دلوں اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا۰۰۹۵ میں ) کہا (کہ)کیاا للہ(تعالیٰ)نے ایک بشر کو رسول بناکر بھیج دیا ہے.تفسیر.پہلی آیت میں بتایاتھاکہ میں توبشر رسول ہوں.اس سے زیادہ میراکوئی دعویٰ نہیں.انبیاء کے بشر رسول ہونے کے اعتراض کا جواب اب اس آیت میں بتایاگیا ہے کہ انبیاء پر جو بڑے بڑے اعتراض ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بشر رسول ہیں.یہ اعتراض ایک نہیں بلکہ ان الفاظ میں کئی قسم کے اعتراض آجاتے ہیں.بعض لوگوںکویہ اعتراض ہوتاہے کہ اللہ تعالیٰ جو بڑی شان کاہے بشرکو رسول بناہی کیونکر سکتاہے.یہ لوگ کلام الٰہی کے نزول ہی کے منکر ہوتے ہیں.بعض لوگ بشر رسول کے منکر تکبر اور ضد کی وجہ سے ہوتے ہیں.یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی انسان ہیں.جیساکہ یہ ہے اگراللہ تعالیٰ نے کلام بھیجنا تھا.توہم سب پر نازل کرتا.اسے کیوں مخصوص کیا گیا.اس لئے ہم اسے نہیں مان سکتے.یہ لوگ کلام الٰہی کے نزول کوناممکن قرار نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کوبڑاسمجھنے کی وجہ سے یہ نہیں تسلیم کرسکتے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے بڑے آدمیوں کی طرف بقول ان کے ایک گھٹیا درجے کے انسان کو پیغام دے کرکیوں بھجوائےگا.ایک تیسراگروہ بشررسول کاانکار اس وجہ سے کرتاہے کہ اس کے نزدیک بشراپنی ذات میں کامل ہے.اور کسی بشر کوالہا م کی ضرورت نہیں.بلکہ اپنی جبلّی طاقتوں کی وجہ سے وہ اپنے لئے خود صحیح راستہ تلاش کرسکتاہے.ایک چوتھاگروہ بشررسول پر اس لحاظ سے معترض ہوتاہے کہ ان کے نزدیک رسول کے لئے بشریت سے زیادہ طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے.ان کے سامنے ایک کمزور سے کمزور وجود کو یہ کہہ کر پیش کردوکہ یہ مافوق الانسانیت طاقتیں رکھتاہے.توفوراً ا س کے ماننے کے لئے
Page 435
تیار ہوجائیں گے.لیکن قوت قدسیہ اورقوت عملیہ کاعملی نمونہ دکھانے والا انسان جوجھوٹے فخر اورجھوٹے دعووں سے بچتاہو.ان کے نزدیک ہرگز قابل اعتنا نہ ہوگا.کیونکہ ان کی طبائع عجوبہ پسندی کاشکار ہوتی ہیں.ایسے لوگ بعض دفعہ بعض پہلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں لیکن نئے نبی کے آنے پر ان کی طبیعت کے اس نقص کاظہور بتادیتا ہے کہ پہلے نبی پر بھی ان کاایمان محض رسمی اورورثہ کاایمان تھا.قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنَ۠ تو(انہیں )کہہ (کہ )اگرزمین پرفرشتے (بستے)ہوتے جو زمین پر اطمینان سے چلتے پھر تے تو(اس صورت میں) لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا۰۰۹۶ ہم ضروران پر آسمان سے کسی فرشتہ کو (ہی )رسول بناکراتارتے.تفسیر.ملائکہ سے مراد فرشتہ خصلت انسان ہیں اس آیت سے معلوم ہوتاہے کہ ملائکہ سے مراد فرشتہ خصلت انسان ہیں.ورنہ فرشتے پردوسرافرشتہ آنے کی کیاضرورت ہے.اس آیت میں اس قسم کے لوگوں کے خیال کا جواب دیا ہے جویہ سمجھتے ہیں کہ و ہ بڑے لوگ ہیں.اوران کوبراہ راست الہام ہوناچاہیے تھا.فرماتا ہے کہ فرشتہ فرشتہ خصلت پر اترتاہے غیر جنس پر نہیں.تم فرشتے بن جاتے توتم پر بھی فرشتے اترتے پرتم تو شیطان بن گئے ہو تم پر فرشتے کس طرح اتریں.دوسرے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جویہ سمجھتے ہیں.کہ بشر سے بڑی طاقتوں والے وجود کی ضرورت تھی.بشرکام نہیں دے سکتا.انہیں یہ بتایا ہے.کہ ہرجنس کے لوگوںکو ان کا ہم جنس ہی نجات دے سکتاہے.کیونکہ نمونہ وہی ہو سکتا ہے جوان میں سے ہو.پس بشر کے سوادوسری جنس بطوررسول انسانوں میں نہیں آسکتی.کیونکہ وہ ان کے لئے نمونہ نہیں بن سکتی.ا ن معنوںکے روسے رسول کے معنی صرف وحی لانے والے کے نہیں ہوں گے بلکہ رسالت کی وہ سب شرائط جن کے ساتھ بشررسول آتے ہیں مراد لی جائیں گی.
Page 436
قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ١ؕ اِنَّهٗ كَانَ تو(انہیں )کہہ(کہ )میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طورپر اللہ ہی کافی ہے.وہ اپنے بندوں کو بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًۢا بَصِيْرًا۰۰۹۷ جاننے والا(اور)دیکھنے والا ہے.تفسیر.انسان کو حقیر ناقابل الہام سمجھنے والے معترضین کو جواب اس میں اس اعتراض کے دوسرے پہلوئوں کا جواب دیا ہے.یعنی ان کوبھی جو انسان کوحقیر سمجھتے ہیں اورالہام کے ناقابل.اوران کو بھی جو انسان کو کامل سمجھتے ہیں اورالہام سے مستغنی.اورجواب یہ دیاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوخوب سمجھتا ہے کہ وہ کتنے کمزور ہیں یاکتنے طاقتورہیں.پس جب اس نے مجھے رسول بناکربھیجا ہے توتمہارایہ توحق ہے کہ اس امر کی تحقیق کرو کہ میں نبی ہوں یا نہیں.اوراس کے لئے میں خدا تعالیٰ کی عملی گواہی پیش کرتاہوں.جب قول کے ساتھ اس کاعمل شامل ہے توتم میرے دعویٰ کو جھوٹاکس طرح کہہ سکتے ہو.مگربہرحال تم یہ دواعتراض معقولیت کو چھوڑے بغیر نہیں کرسکتے.کیونکہ اگریہ ثابت ہوجائے.کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے.تومانناپڑے گا.کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ تو انسان اس قدرحقیر ہے کہ اسے وہ مکالمہ مخاطبہ کافخر نہیں دے سکتا.اورنہ اس قدرکامل کہ اسے الٰہی کلام کی احتیاج ہی نہیں.وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ١ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ اورجسے اللہ (تعالیٰ)ہدایت دے وہی ہدایت پرہوتاہے.اورجنہیں وہ گمراہ کرے توتُواس کے (یعنی اللہ کے ) لَهُمْ اَوْلِيَآءَ ۱؎مِنْ دُوْنِهٖ١ؕ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى مقابل پر اس کاکوئی بھی مددگار نہیں پائے گا.اورقیامت کے دن ہم انہیں ان کے مقاصد کے مطابق اندھے اور وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّ بُكْمًا وَّ صُمًّا١ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ١ؕ كُلَّمَا
Page 437
گونگے اوربہرے ہونے کی حالت میں جمع کریں گے.ان کاٹھکانا جہنم ہوگا.جب بھی وہ (ذرا) خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا۰۰۹۸ ٹھنڈی ہوگی توہم ان پرآگ (کاعذاب اوربھی) بڑھادیںگے.۱؎ اولیآء.اَوْلِیَآءُ جمع وَلِیٌّ کی ہے جس کے ایک معنی مددگار کے ہیں لیکن ترجمہ میں جمع کی جگہ مفرد ترجمہ کیاگیاہے.کیونکہ اردومیں ایسے موقعہ پر مفرد ہی بولاجاتا ہے.حلّ لُغَات.وجوھھم.وُجُوْہٌ وجْہٌ کی جمع ہے.اور وَجْہٌ کے معنے ہیں.اَلْقَصْدُ وَالنِّیَّۃُ.مقصد.اَلْمَرْضَاۃُ.پسندیدہ طریق.(اقرب) خَبَتْ.خَبَتِ النَّارُ وَالْحَرْبُ وَالْحِدَّۃُ کے معنے ہیں سَکَنَتْ وخَمَدَتْ وَطَفِئَتْ.آگ.جنگ یاتیزی دھیمی یاٹھنڈی پڑ گئی.کمزورہوگئی.بجھ گئی (اقرب) سعیرا اَلسَّعِیْرُ کے معنے ہیں اَلنَّارُ وَلَھَبُھَا.آگ.شعلے.(اقرب) تفسیر.انجام ہی فیصلہ کن ہوتا ہے چونکہ پچھلے سوالوں اورجوابوں سے کفار کی کج بحثی کاثبوت ملتاتھا.اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تسلی دلائی کہ ان باتوںسے گھبرانانہیں چاہیے.ہدایت اورگمراہی کافیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.جومستحق ہدایت ہو اسے ہدایت مل جاتی ہے خواہ درمیا ن میں کتنی روکیں پیداہو ں.اور جو مستحق ہدایت نہ ہو و ہ گمراہ ہی رہتاہے یاآخر گمراہ ہو جاتا ہے خواہ بظاہر اس کے لئے سہولتیں میسر ہوں پس ان ظاہری حالات سے مایوس نہ ہوناچاہیے.بعض دفعہ شدیدمخالف اوربظاہر کج بحث لوگ آخر میں ایمان لے آتے ہیں.اوراخلاص کانہایت اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں.اصل توانجام کودیکھناچاہیے.جس کاانجام خراب ہو خطرہ تو ا س کے لئے ہے.خَبَتِ النَّارُ وَالْحَرْبُ وَالْحِدَّۃُ سَکَنَتْ وَخَمَدَتْ وَطَفِئَتْ.یعنی آگ، لڑائی اورتیزی کے متعلق خَبَتْ آتاہے جس کے معنے ہیں جوش جاتارہا.کم ہوگیا.بالکل ٹھنڈاپڑ گیا.قیامت کے دن مونہوں کے بل گھسیٹے جانے سے مراد عَلٰى وُجُوْهِهِمْ کے متعلق قرآن کریم میں دوسری جگہ آتاہے يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ (القمر:۴۹) جس دن وہ مونہوں کے بل گھسیٹ کرآگ میں ڈالے
Page 438
جائیںگے.اس آیت کا بھی یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کفار مونہوں کے بل گھسیٹ کرڈالے جائیں گے.بخاری اورمسلم میں انس ؓ سے روایت ہے کہ اِنَّ الَّذِیْ اَمْشٰھُمْ عَلَی اَرْجُلِھِمْ قَادِرٌ عَلَی اَنْ یُمْشِیَہُمْ عَلٰی وُجُوْھِھِمْ (مسند احمدمسند المکثرین من الصحابۃ مسند أنس بن مالک) کہ جس خدا نے ان کو پائوں کے بل چلایا ہے.وہ اس بات پربھی قادر ہے کہ ان کومونہوں کے بل چلائے.پھر ایک روایت میں ہے کہ تین طرح حشرہوگا.کچھ سوارہوںگے.کچھ پیدل اوراوربعض مونہوں کے بل(روح المانی زیر آیت ھذا) ایک اورروایت میں ہے تُجَرُّوْنَ عَلٰی وُجُوْھِکُمْ.دوزخیوںکوان کے مونہوں کے بل گھسیٹاجائے گا.(روح المانی زیر آیت ھذا) معلوم ہوتا ہے کہ سوار توانبیاء ہیں اورپیدل چلنے والے مومن ہیں اورمونہوں کے بل گھسیٹے جانے والے کافرہیں.چونکہ آخرت میں ہرچیز ایک انعکاسی رنگ رکھے گی.اس لئے ان کے وہ اعمال جن کو وہ دنیا میں کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی طرف نظر نہیں رکھتے تھے.بلکہ سفلی اورارضی اغراض پر ان کی نظر ہوتی تھی.قیامت کے دن ان پر اس رنگ میں متمثل ہوں گے کہ اوندھے منہ زمین پر چلیں گے.منہ کے بل چلنے کے معنے دوڑنے کے بھی ہیں (۲)عربی کا ایک اورمحاورہ ہے.مَرَّ الْقَوْمُ عَلٰی وُجُوْھِھِمْ اَیْ اَسْرَعُوْا.یعنی وہ قوم دوڑ کرچلی گئی.اس محاور ہ کے روسے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ قیامت کے دن جب ہم ان کا حشرکریں گے توو ہ دوڑ رہے ہوں گے جیسے دوسری جگہ فرماتا ہے مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ (ابراہیم:۴۴)کہ کفا ر سراٹھائے ہوئے دوڑے چلے جائیںگے.اس میں گھبراہٹ کی کیفیت کااظہار کیا ہے.یعنی اس وقت ان میں بے اطمینانی او رگھبراہٹ پائی جائے گی.انسان کو نیت کے مطابق اجر (۳)اَلْوَجْہُ کے معنے عربی زبان میں مَایَتَوَجَّہُ اِلَیْہِ الْاِنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ وَغَیْرِہٖ.اَلْقَصْدُ وَالنِّیَۃُ کے بھی ہوتے ہیں.یعنی وہ کام جن کی طرف انسان توجہ کرتے ہیں اورقصداورنیت کو بھی وجہ کہتے ہیں.ان معنوں کی روسے آیت کایہ مطلب ہوگاکہ ان کے مقاصد اورنیتوں کے مطابق ہم ان کاحشر کریں گے.اگران کامقصد الٰہی سلسلوں سے دشمنی کرناتھا.تووہاں بھی وہ خدا تعالیٰ سے دور اوراس کے دشمنوں کے ساتھ رکھے جائیں گے.گویاہرانسان اپنی اپنی نیت کے مطابق جزاء پائے گا.چونکہ اگلے جہان کے متعلق کفار کاکوئی مقصد نہیں ہوتا.اس لئے فرمایاکہ وہ وہاں اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے.خَبَت سے یہ مراد نہیں کہ آگ بجھ جائے گی.بلکہ بعض دفعہ کوئی مصیبت زیادہ دیر رہے توحس مٹ جاتی ہے.
Page 439
اسی جگہ ایسی ہی کیفیت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ جب عذاب محسوس کرنے کی حس کمزورہوجائے گی.ہم ان کی حس کو تیز کردیں گے جیسے فرمایا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ (النساء:۵۷) جب ان کے چمڑے پک جائیں گے اورعذا ب کی حس کم ہوجائے گی توہم ان کی جلدیں بدل دیں گے تاکہ عذاب کامزہ چکھتے رہیں.توآگ کاٹھنڈاہونا کفار کی حس کے لحاظ سے ہے نہ کہ خود آگ کی تیزی یاکمی کے لحاظ سے.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہتے ہیں کہ پرنالہ چلتاہے.حالانکہ پرنالہ نہیں چلتا بلکہ پرنالہ میں سے پانی بہہ رہاہوتاہے.ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ قَالُوْۤا ءَاِذَا كُنَّا یہ (آگ)ان (ہی کے اعمال)کی جزاہوگی کیونکہ انہوں نے ہمارے نشانوں کاانکارکیا.اورکہا(کہ )کیاجب ہم عِظَامًا وَّ رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ۠ (مرکر)ہڈیاں اورچوراچوراہوجائیں گے (توہمیں ازسرنو زندہ کیا جائے گا اور)کیاواقعی ہمیں ایک نئی مخلوق کی خَلْقًا جَدِيْدًا۰۰۹۹ صور ت میں اٹھایاجائے گا.تفسیر.یعنی یہ عذاب کلام الٰہی کے انکار کے سبب سے ہوگا.اوریہ کلام الٰہی کاانکار درحقیقت بعد المو ت زندگی پرایمان نہ ہونے کی وجہ سے پیداہواہے.قرآن کریم نے اس امر پر بہت ہی زوردیا ہے کہ مذہب کے انکار یا ا س کی تخفیف کی اصل وجہ بعد الموت زندگی کاانکار ہے.اس میں واعظوں اوراستادوں اوراماموں اورمربّیوں کے لئے ایک بہت بڑاسبق ہے.بچپن سے بعث بعد الموت کے دلائل نوجوانوں کے ذہن نشین کرنے چاہئیں.اس کے بغیر کبھی صحیح اورعمد ہ تربیت نہیں ہوسکتی.یہ آیات یہود پر بھی چسپاں ہوتی ہیں.کیونکہ ان میں سے اکثر بعث بعد الموت کے منکر تھے.اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ قَادِرٌ کیاو ہ (ابھی تک )سمجھ نہیں سکے کہ وہ (ہستی)جس نے آسمانوں اورزمین کوپیدا کیا ہے.اس بات پر(بھی )قادر
Page 440
عَلٰۤى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ ہے.کہ وہ ان جیسے (اورلوگ )پیداکرے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ان کے لئے ایک میعاد مقرر کردی فِيْهِ١ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا۰۰۱۰۰ ہے پھر(بھی)ان ظالموں نے کفر(کی راہ اختیار کرنے )کے سواہربات سے انکار کردیا ہے.تفسیر.مسلمانوں کی ترقی قیامت کا ثبوت ہے ان کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ دوبار ہ پیداکرسکتا ہے کیونکہ یہ صر ف دعویٰ ہوتاجس کے پیش کرنے کاکوئی فائدہ نہ تھا.پس جواب میں یہ فرمایاکہ کیا تم ا س پریقین رکھتے ہو کہ تم کو ہلاک کرکے خدا تعالیٰ تمہاری شان و شوکت کسی دوسری قوم کو دےدے.پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ کفار اس با ت پر کبھی یقین نہ کریں گے بلکہ بڑی شدت سے اس کا انکار کریں گے پس یہی دلیل ہم ان کے سامنے بعث بعد الموت کی پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو بعث بعدالموت کی خبر دیتا ہے.اس نے یہ خبر بھی دی ہے کہ دشمنان اسلام کی حکومت مٹادی جائے گی اوران کی جگہ مسلمانوں کو دے دی جائے گی.اگریہ بات پوری ہوجائے تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ دوسری بات بھی عالم الغیب اور قادر خدا کی طرف سے ہے.یہ بات کس شان سے پوری ہوئی ؟ عرب، ایران،روم اورمصر چند سالوں میں یکے بعد دیگرے اسلامی ضرب کی تاب نہ لاکر سرنگوں ہوگئےاورفاقہ کش مزدوردنیاکے بادشاہ ہوگئے.اس حشر کاپیداکرنے والا کیادوسرے حشر سے عاجز آسکتاہے بعث بعدالموت کوعجیب سمجھنے والے وقوع سے پہلے کیا اس خبر کو بھی ویساہی عجیب نہ سمجھتے تھے.قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآىِٕنَ رَحْمَةِ رَبِّيْۤ اِذًا تو(انہیں)کہہ(کہ)اگر تم میرے رب کی رحمت کے (غیر متناہی)خزانوں کے (بھی)مالک ہوتے تو(بھی )تم لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ١ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًاؒ۰۰۱۰۱ (ان کے )خرچ ہوجانے کے ڈرسے (انہیں )روک ہی رکھتے.اورانسان بڑاہی کنجوس ہے.حلّ لُغَات.اَمْسَکْتُمْاَمْسَکْتُمْیہ اَمْسَکَ سے جمع کاصیغہ ہے.اَمْسَکَ الشَّیْء بِیَدِہٖ :
Page 441
َبَضَہٗ کسی چیز کوہاتھ سے پکڑا.اَمْسَکَ الْمَتَاعُ عَلٰی نَفْسِہِ.مال اپنے لئے روک رکھا.اَمْسَکَ عَنِ الْاَمْرِ : کَفَّ عَنْہُ وَامْتَنَعَ.کسی امر سے رک گیا.(اقرب) قتورًا.قَتُوْرًا یہ قَتَـرَ سے مبالغہ کاصیغہ ہے.قَتَرَ عَلی عَیَالِہِ :ضَیَّقَ عَلَیْھِمْ فِی النَّفَقَۃِ.اہل وعیال کے خرچ میں تنگی کی.قَتَرَالشَّیْءَ.ضَمَّ بَعْضَہُ اِلَی بَعْضٍ.کسی چیز کواکٹھا کیا اورجوڑ جوڑ کررکھا.اَلْقَتُوْرُ اَلْمُضَیِّقُ عَلٰی عِیَالِہِ فِی النَّفَقَۃِ.اپنے خانگی خرچ میں بخل کرنے والا.اَلْبَخِیْلُ.کنجو س (اقرب) الانفاق.اَنْفَقَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں اِفْتَقَرَوَ فَنِیَ زَادُہُ.وہ مفلس ہوگیا.اوراس کاخرچ ختم ہوگیا.اَنْفَقَ مَالَہُ.صَرَفَہُ وَأَنْفَدَہُ.اس نے اپنامال خرچ کرکے ختم کردیا (اقرب)پس اَلْاِنْفَاقُ کے معنے ہوںگے (۱)مفلس ہوجانا (۲)مال خرچ کردینا (۳)مال کا خرچ ہوجانا.تفسیر.یہاں پھر قُلِ الرُّوْحُ والے مضمو ن کی طرف رجوع کیا ہے.اوربتایاہے.کہ خدائی الہام اور روحانیوں میں یہ فرق ہے کہ خدا کاکلام لانے والے توبے دریغ آسمانی خزانے لٹاتے ہیں.اورانہیں حکم ہوتاہے کہ بَلِّغْ بَلِّغْ.لیکن یہ روحانی کہلانے والے اسراء اوراشار وں میں عمر بسر کرتے ہیں قسمیں لے لے کر اپنے شاگردوں کو گربتاتے ہیں یہ لوگ دنیاکے لئے ہادی اورراہنما کس طرح ہوسکتے ہیں.یہ مرض آج کل کے صوفیا ء میں بھی پیداہوگیاہے.ایک دفعہ میں نے ذکرالٰہی کے متعلق تقریر کی.اوراس کے بہت سے طریقے اورفائدے بیان کئے.ایک صاحب نے دوران تقریر میں رقعہ لکھا کہ آپ کیاغضب کررہے ہیں.ان میں سے ایک ایک نکتہ صوفیا ء دس دس سال خدمت لے کر بتایاکرتے تھے.آپ ایک ہی مجلس میں سب راز کھولنے لگے ہیں.حق یہ ہے کہ مذہب میں کوئی راز نہیں.اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے متعلق یہ چاہتاہے کہ وہ اس کے قرب کے اعلیٰ درجوں کوحاصل کریں اوراسے بندوں کی ترقیات میں روک ڈالنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں کیونکہ وہ غیرمحدود ہے.اوراس تک پہنچنے کی منازل بھی غیر محدود ہیں اسے یہ ڈر نہیں کہ ایک دن علم ختم ہوجائے گا.اورپھر میرے پاس بنانے کو کچھ نہ رہے گا.اورمیں اور میرے بندے برابر ہوجائیں گے.لیکن یہ نام نہاد روحانی ایک محدود علم رکھتے ہیں جس کااکثر حصہ جھوٹاہوتاہے.وہ اگراپنی سب باتیں بتادیں تودوسرے ہی دن ان کوپوچھنے والاکوئی نہ رہے.چنانچہ آئے دن یہ نظارے نظر آتے ہیں کہ ایک پیر نے دوسرے کو خلیفہ بنایااوراس نے جھٹ جاکر الگ گدی بنالی.مگرخدارسیدہ شخص کا کوئی شاگرد اس پر ایما ن رکھتے ہوئے جدانہیں ہوسکتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کاعلم جوخدا سے آتاہے کبھی ختم نہیں ہوسکتا.اس لئے اس سے جدائی اپنے علم کی ترقی روکنے کے مترادف
Page 442
ہے.غرض نام نہاد روحانی لوگ سالہا سال خدمت لے کر ایک اسم یانقش اسی لئے بتاتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جوکچھ ہے جلد ختم ہوجائے گا.مگراللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علوم اول توختم نہیں ہوتے اور اگرہوجائیں تووہ اور پیداکردیتاہے.اس لئے یہ جسمانی کسب الہا م کاقائم مقام کسی صورت میں نہیں ہوسکتا.وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اورہم نے موسیٰ کو یقیناً نوروشن نشان دیئے تھے.چنانچہ توبنی اسرائیل سے (ان حالات کوپوچھ ) اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى جب وہ ان (یعنی اہل مصر)کی طرف آیاتھا.توفرعون نے اس سے کہا تھا (کہ )اے موسیٰ مَسْحُوْرًا۰۰۱۰۲ میں یقیناًتجھے فریب خوردہ سمجھتاہوں.حلّ لُغَات.مَسْحُورًا.مَسْحُوْرًایہ سَحَرَسے اسم مفعو ل ہے.سَحَرَہٗ:عَمِلَ لَہ السِّحْرُ وَخَدَعَہُ ٗ سَحَرَہُ کے معنے ہیں اس پرجادوکیا.اسے فریب دیا.سَحَرَہٗ عَنِ الْاَمْرِ :صَرَفَہُ.اس کو کسی بات سے ہٹادیا.سَحَرَ بِکَلَامِہِ وَالْحَاظِہِ:اِسْتَمَالَہُ وَسَلَبَ لُبَّہٗ.اسے باتوں اورنظروں سے اپنی طرف مائل کرلیا.اوراس کی عقل کولُبھالیا.(اقرب) تفسیر.بنی اسرائیل کے نو نشانوں کی تفصیل تِسْعَ اٰيٰتٍ.قرآن مجید میں دوسری جگہ ان نشانوں کی تفصیل موجود ہے اوروہ یہ ہیں.(۱)عصا.جیسا کہ فرماتا ہے فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ(الاعراف :۱۰۸) (۲)یدِبیضاء جیسے کہ فرماتا ہے وَّ نَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ(الاعراف :۱۰۹)(۳)قحط جیساکہ فرماتا ہے وَ لَقَدْ اَخَذْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ (الاعراف :۱۳۱)(۴)پلوٹھوں کی موت.جیسے فرماتا ہے وَ نَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ(الاعراف :۱۳۱)اس جگہ ثمرات سے مراد ثمرئہ قلب یا ثمرئہ فؤاد ہے جس نام سے بیٹو ں کوپکاراجا تا ہے.(۵)طوفان (۶)ٹڈی (۷)جوئیں یا کھٹمل کاعذاب(۸)مینڈکوں کاعذاب(۹)خون کاعذاب.یعنی ایسی امراض
Page 443
کاعذاب جن سے انسان کاخون ضائع یا خراب ہو.جیسے نکسیروں کاپھوٹنا.اورایک خاص مرض بھی اس وقت پیداہواتھا.یعنی ایک قسم کے پھوڑے نکلتے تھے جن میں سے کثرت سے خون بہتاتھا.جیساکہ فرماتا ہے فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ(الاعراف :۱۳۴).بائیبل میں ان نو عذابوں کی عجیب وغریب تشریح لکھی ہے.جس کے ماننے اورجاننے کی ہمیں ضرورت نہیں.ہمیں صرف اس امرسے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کونو نشان عطافرمائے جووقفہ وقفہ کے بعدظاہر ہوئے جیسا کہ مفصّلات کے لفظ سے ظاہر ہے.حضرت موسیٰ اوران کے نشانات کا ذکرکرکے یہود کوتوجہ دلائی ہے کہ جس طر ح فرعون کو نشان دکھائے گئے تھے یہود کوبھی نشان دکھائے جائیں گے.مگرجس طرح فرعو ن نے فائدہ نہ اٹھا یاوہ بھی نہ اٹھائیں گے اورآخر معنوی طور پر غرق کئے جائیں گے.اس آیت سے اس امر کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود پربھی نوقسم کے عذاب نازل ہوں گے یانو نشان دکھائے جائیں گے.مگر مجھے اب تک تاریخ پر اس بارہ میں غور کرنے کاموقعہ نہیں ملا.قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاۤ اَنْزَلَ هٰؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ اس نے کہا (کہ)تجھے یقیناً علم ہوچکا ہے کہ ان (نشانات)کوآسمانوں اورزمین کے رب نے ہی بصیر ت بخشنے الْاَرْضِ بَصَآىِٕرَ١ۚ وَ اِنِّيْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا۰۰۱۰۳ والابناکر اتاراہے.اوراے فرعون میں تیری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ توہلا ک ہوچکا ہے.حلّ لُغَات.بَصَائِر.بَصَائِرُیہ بَصِیْرَۃٌ کی جمع ہے اَلْبَصِیْرَۃُ کے معنے ہیں.اَلْعَقْلُ.عقل.اَلْفِطْنَۃُ.ذہانت.مَایُسْتَدَلُّ بِہ جس سے راہنمائی اوربصیرت حاصل ہو.اَلْحُجَّۃُ.دلیل.اَلْعِبْرَۃُ.عبرت.اَلشَّاھِدُ.گواہ(اقرب) مَثْبُورًامَثْبُورًایہ ثَبَرَسے اسم مفعول ہے ثَبَرَہُ کے معنے ہیں.خَیَّبَہٗ.اسے نامرادو ناکام کیا.لَعَنَہٗ.اس پر لعنت کی.طَرَدَہُ.اسے دھتکارا.ثَبَرَہٗ عَنِ الْاَمْرِ :مَنَعَہٗ وَصَرَفَہٗ اسے روک دیا.ہٹادیا.ثَبَرَاللہُ
Page 444
زَیْدًا:اَھْلَکَہُ اِھْلَاکًادَائِمًا لَایَنْتَعِشُ بَعْدَہٗ.اللہ نے اسے ایساتباہ کیا کہ پھر و ہ سنبھلنے کے قابل نہ رہا.(اقرب) تفسیر.موسیٰ نے کہا اے فرعون تیرادل جانتاہے.کہ ان نشانات کوآسمان و زمین کے خدا نے بصیر ت کے طورپر نازل کیا ہے اورمجھے یقین ہے کہ توہلا ک کیاجائے گا.یایہ کہ تونے جو مجھے مسحور کہہ کر بدنام اورکمزورکرنے کی تدبیر سوچی ہے.خداتجھے اس میں کامیا ب نہ کرے گا بلکہ تواس اراد ہ میں خائب وخاسر ہوگا.کیونکہ مثبورکے ایک معنے ناکام و نامراد کے بھی ہیں.اس ذکر سے یہ بتانامقصود ہے کہ جس طرح تم نشان پر نشان دیکھتے ہومگرفریبی اوردھوکا باز کہتے جاتے ہو.ایسا ہی اس سے پیشتر فرعون نے موسیٰ کو کہاتھا.مگرجانتے ہواس کاانجام کیاہواتھا ؟ فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ۠ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ اس پراس نے ان (کی بنیادوں )کواس ملک سے اکھاڑ دینے کاارادہ کرلیا.توہم نے اسے اورجواس کے ساتھ جَمِيْعًاۙ۰۰۱۰۴ تھے سب کو غرق کردیا.تفسیر.یعنی اس نے بھی چاہاتھا کہ ان کو ملک سے ذلیل کرکے نکال دے.مگرخود غرق ہوگیا.اہل کتاب نے کفار سے سازش کرکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوقیصر کی فوج سے لڑانے کے لئے بھجوادیاتھا مگرخدا نے ان کی تدبیر کوناکام کیا.اورآپ ؐ تبوک سے بغیر کسی نقصان کے باعزت واپس آئے(تاریخ الخمیس جلد۲ غزوۃ تبوک).وَّ قُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ اور اس کے(ڈوب مرنے کے )بعد بنی اسرائیل کو ہم نے کہہ دیا (کہ )تم اس (موعود)ملک میں (جاکر آرام سے ) وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًاؕ۰۰۱۰۵ رہو.پھر جب پچھلی بار کاوعدہ (پوراہونے کا وقت )آئے گا.توہم تم (سب )کو جمع کرکے لے آئیں گے حلّ لُغَات.لَفِیْفًا.لَفِیْفًایہ لَفَّ سے فعیل کے وز ن پر بمعنی مفعول ہے.لَفَّہٗ کے معنے ہیں.ضَمَّہٗ سمیٹا.جَمَعَہٗ ا س کوجمع کیا.لَفَّ الشَّیْءَ بِالشَّیْءِ :ضمَّہٗ اِلَیْہِ وَ وَصَلَہُ بِہٖ ایک چیز کودوسری سے ملادیا.لَفَّ
Page 445
الْکَتِیْبَتَیْنِ :خَلَطَ بَیْنَہُمَا فِی الْحَرْبِ.جنگ میں دودوستوں کو آپس میں ملا دیا.اَللَّفِیْفُ:اَلْمَجْمُوْعُ.جمع کیا ہوا.مَااجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ مِنْ قَبَائِلَ شَتّٰی.مختلف قوموں کے آدمیوں کی جماعت (اقرب) تفسیر.اُسْكُنُوا الْاَرْضَ.اس سے مراد مصر کی سرزمین نہیں.کیونکہ مصر میں تووہ نہیں آباد ہوئے اس سے مراد ملک کنعان ہے یعنے وہ ملک جس کاتمہیں وعدہ دیاگیاہے.گویاالارض سے مراد معہود ذہنی ہے.آنحضرت ؐ کی فضیلت موسیٰ پر وطن واپس ملنے کے ذریعہ سے رسول کریم صلعم کو موسیٰ علیہ السلام پر یہ فضیلت ہے کہ ان کو جو جگہ ملی وہ مصر کے قائم مقام تھی.مصرنہیں ملا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وہ جگہ ملی جوآ پ کاوطن تھا اورپھر دشمنوں کے ملک بھی ہاتھ آئے.فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ.یعنی اب تم کنعان میں جائو.لیکن ایک وقت کے بعد تم کو وہاں سے نکلنا پڑے گا پھر خدا تعالیٰ تم کو واپس لائے گا پھر تم نافرمانی کروگے اوردوسری دفعہ عذاب آئے گا اس کے بعد تم جلاوطن رہوگے یہاں تک کہ تمہاری مثیل قوم کے متعلق جو دوسری تباہی کی خبر ہے اس کا وقت آجائے اس وقت پھر تم کو مختلف ملکوں سے اکٹھاکرکے ارض مقدس میں واپس لایا جائے گا.مسلمانوں کی مماثلت بنی اسرائیل سے ترقی اور تنزل کے لحاظ سے اس آیت سے ظاہر ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے لئے دوتباہیوں کی خبر اس سورۃ کے شروع میں دی گئی تھی ویسی ہی خبر مسلمانوں کے لئے بھی دی گئی ہے کیونکہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل کامثیل قرار دیا گیا ہے.جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ ؑ کامثیل قراردیاگیا ہے.اوراس کاثبوت یہ ہے کہ سورۃ کے شروع میں دووعدوں کا ذکر ہے اوردونوں عذاب کے وعدے ہیں.ایک بخت نصرشاہ بابل کے ہاتھوںپوراہوا.اوردوسراٹائیٹس شاہ روم کے ہاتھ سے پوراہوا.(دیکھو رکوع اول) ان دونوں وعدوں میں بنی اسرائیل کے اکٹھاکرنے کا ذکر نہیں بلکہ ان کے پراگندہ ہونے کا ذکر ہے.اس کے برخلاف اس آیت میں یہ ذکرہے کہ دوسرے وعدے کے وقت بنی اسرائیل کو پھر ارض مقدس میں لایاجائے گا.اس سے معلوم ہواکہ یہ دوسراوعدہ کوئی اورہے اوراس دوسرے وعدے سے یہ بھی معلو م ہواکہ اس دوسرے وعدے کے ساتھ کوئی پہلاوعدہ بھی ہے.اب ہم غورکرتے ہیں توان دو وعدوں کا ذکرقرآن کریم میں صرف اس طرح ملتاہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کومثیل موسیٰ قراردیاگیا ہے.اورسورۃ فاتحہ میں مسلمانوں کے ایک حصہ کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ وہ اہل کتاب کے نقش پر چلیں گے.پس ان دونوں باتوںکوملا کر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں.کہ بنی اسرائیل کی طرح دوعذاب کے وعدے مسلمانوں کے لئے بھی کئے گئے ہیں.اوراس جگہ وَعْدُالْاٰخِرَۃ سے مراد مسلمانوں کے دوسرے عذاب کاوعدہ ہے.اوربتایایہ ہے کہ مسلمانوں پر جب یہ عذاب آئے گا.کہ دوسری دفعہ ارض مقد س کچھ
Page 446
عرصہ کے لئے ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی تواس وقت اللہ تعالیٰ پھر تم کو اس ملک میں واپس لے آئے گا.چنانچہ دیکھ لو اسی طرح واقعہ ہواہے.جس طرح بخت نصرکے وقت میں پہلی دفعہ ارض مقدس یہود کے ہاتھ سے نکلی.اسی طرح صلیبی جنگوں کے وقت مسلمانوںکے ہاتھ سے نکلی(دی نیو انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Crusade).پھر جس طرح موسیٰ سے تیرہ سوسال بعد حضرت مسیح ؑ کے صلیب کے واقعہ کے بعد جبکہ گویاوہ بظاہر اس ملک کے لوگوں کے لئے مرگئے تھے.بنی اسرائیل کو ارض مقد س سے دوبارہ بے دخل کردیاگیا.اسی طرح اس زمانہ میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اتنا ہی عرصہ گذراہے مسلمانوں کی حکومت پھر ارض مقد س سے جاتی رہی ہے.اورجیساکہ قرآن کریم نے فرمایاتھا مسلمانوں کایہ دوسراعذاب یہودکے لئے ارض مقدس میں واپس آنے کاذریعہ بن گیا ہے.تفسیر فتح البیان کے مصنف اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ بعض علما ء کے نزدیک وَعْدُالْاٰخِرَۃ سے اس جگہ مسیح موعود کانزول مراد ہے ان علماء کایہ قول میری تفسیر کی تائید کرتاہے.وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ١ؕ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا اوراس (قرآن )کو ہم نے حق(وحکمت)کے ساتھ ہی اتاراہے.اورحق (وحکمت )کے ساتھ ہی یہ اُتراہے وَّ نَذِيْرًاۘ۰۰۱۰۶ اورہم نے تجھے صرف بشارت دینے والااور(عذاب سے )آگا ہ کرنے والا بناکر بھیجا ہے.تفسیر.یعنی یہ خبر ضرورپوری ہو کررہے گی.چونکہ موسیٰ ؑ کی پیشگوئی کے سلسلہ میںرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کا ذکر بھی آگیا.کہ مسلمانوں پر بھی دوکٹھن زمانے آنے والے ہیں.اس لئے اس آیت سے اس مضمون کی تائید کی گئی ہے.آنحضرتؐ کی وحی میں دخل شیطان کی تردید اس آیت سے ضمناً اس خیال کی بھی تردیدہوتی ہے.جولوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں شیطان دخل دے دیتاتھا.کیونکہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کوحق سے اتاراہے اوروہ محمد رسول اللہ تک حق سے ہی اُتراہے.پس جبکہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حق سے اترآیاتوشیطان کو دخل دینے کاموقعہ کب ملا.
Page 447
آخر میں فرمایا کہ تجھے بھی موسیٰ کی طرح بشیر و نذیر بناکر ہم نے بھجوایاہے.پس جس طرح اس کی قوم نے ترقی کی.اسی طرح تیری قوم بھی ترقی کرے گی.اورجس طرح اس کے دشمن ہلاک ہوئے تیرے دشمن ہلاک ہوں گے.وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّ نَزَّلْنٰهُ اور(اسے )قرآن بناکر (اُتاراہے )اس حال میں کہ ہم نے اسے (کئی)ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تُواسے تَنْزِيْلًا۰۰۱۰۷ (سہولت اور)آہستگی کے ساتھ لوگوں کوپڑھ کرسناسکے اورہم نے اسے تھوڑاتھوڑاکرکے نازل کیاہے.حلّ لُغَات.فَرَقْنٰہُ.فَرَقَ بَیْنَہُمَا:فَصَلَ اَبْعَاضَہُمَا.دوچیزوں کے ٹکڑوں کو علیحدہ علیحدہ کیا.فَرَقَ لَہُ عَنِ الشَّیْءِ:بَیَّنَہٗ.اسے کھو ل کربا ت بتائی (اقرب) وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰہُ اَیْ بَیَّنَّا فِیْہِ الْاَحْکَامَ وَ فَصَّلْنٰہُ.وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ کے معنے ہیں ہم نے اس میں احکام بیان کئے ہیں.اوراس کے جداجداحصے بنائے ہیں.وَقِیْلَ اَنْزَلْنٰہُ مُفَرَّقًا اورفَرَقْنٰہُ کے یہ معنی بھی کئے گئے ہیں.کہ ہم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کرکے اُتارا ہے.(مفردات ) مُکْثٍ مُکْثٍ مَکَثَ یَمکُثُ کامصدرہے.مَکَث کے معنی ہیں.لَبِثَ.رُکا.ٹھہرا.رَزُنَ.آہستہ وباوقار ہوا(اقرب)اَلْمُکْثُ.ثُبَاتٌ مَعَ إِنْتِظَارٍ.ایسا توقف جس میں انتظا ر بھی ہو (مفردات ) تفسیر.قُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُکے معنے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے کرکے ناز ل فرمایا ہے.یعنی ایک ہی وقت میں کئی کئی سورتوں کی آیات اُترتی رہتی ہیں.اورپھر پہلی اتری ہوئی سورۃ پیچھے کردی جاتی ہے اوربعد کی پہلے.اس پر جو اعتراض پڑتاتھااس کاجوا ب دیا ہے کہ ایسااس لئے کیا گیاہے کہ تُواسے اپنی جگہ ٹھہر کرپڑھ سکے یعنی تیرے اندر بے اطمینانی او رگھبراہٹ پیدانہ ہو.یہ جوا ب دیکھو اعتراض کرنے والوں کے لئے کیسامسکت ہے.تنزیل قرآن میں عارضی اور مستقل ضرورت دونوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب دو قسم کے تھے.ایک عارضی یعنی ا س وقت کے کفار اورایک مستقل یعنی مومن اوربعد میں آنے والے لوگ.مستقل ضرورت کے لئے قرآن کریم کی اَورترتیب چاہیے تھی اورعارضی ضرورت کے لئے اور.مستقل ضرورت کے لئے جن سورتوں کو آخر میں نازل کرناچاہیے تھا.عارضی ضرورت کے لئے ان کی فوری ضرورت تھی.
Page 448
اسی طرح ایک سورۃ کے بعض مضامین کی ضرورت آخرمیں تھی بعض کی شروع میں.اگرعارضی ضرورت کو مدنظر نہ رکھاجاتا توسالہا سال تک مسلمان کفار کوصحیح جواب نہ دے سکتے.اوراگر مستقل ضرورت کو نظرانداز کردیاجاتا.توقرآن آئندہ زمانہ میں ایسا مفید نہ ہوتاجیسااب ہے.پس فرمایا ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے اتارا.جوں جوں ضرورت تھی اُتارتے گئے.بعد والے مضمون کوپہلے.پہلے کے مضمون کوبعد میں.تاکہ وقتی ضرورت پو ری ہوجائے.اوربعد میں حکم دےکر مستقل ضرورت کے مطابق اس کی ترتیب کردی.جیسے دوسری جگہ فرماتا ہے.اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ(القیامۃ :۱۸)کہ اس کی آخری ترتیب ابھی نہیں ہوئی جب یہ وحی کے متفرق ٹکڑے اُترچکیں گے.توہم از سرنو ا س کتاب کوترتیب دیں گے.اورپھر وہ اس ترتیب کے مطابق پڑ ھی جائے گی.اس آیت میں اس شبہ کا جواب دیاگیا ہے کہ اس سورۃ میں بعض ایسے مضامین کا جواب ہے جوبعد میں نازل ہونے والی سورتوں سے تعلق رکھتے ہیں.قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا١ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ تُو(انہیں )کہہ(کہ)تم اس پر ایمان لائو یانہ لائو.جن لوگوں کو ا س (کے نزول)سے پہلے (الہامی صحیفوں یا فطرت قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ صحیحہ کے ذریعہ سے)علم دیاجاچکا ہے جب ان کے سامنے (اسے )پڑھاجاتا ہے تووہ (اسے سن کر )کامل لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًاۙ۰۰۱۰۸ فرمانبرداری اختیار کرتے ہو ئے ٹھوڑیوں کے بل گرجاتے ہیں.حلّ لُغَات.الاذقان : اَلْاَذْقَانُ ذَقَنٌ کی جمع ہے.اور ذَقَنٌ کے معنے ٹھوڑی کے ہیں.ذَقَنَ کالفظ عربی محاورہ کے رُو سے تذلل پر دلالت کرنے کے لئے بولاجاتاہے.کہتے ہیں.مُثْقَلٌ اِسْتَعَانَ بِذَقَنِہِ.یُضْرَبُ لِمَنْ اِسْتَعَان بِأَذَلَّ مِنْہُ.کہ فلاں نے اپنے سے بھی ذلیل انسان سے مدد چاہی(اقرب)پس یخِرُّوْنَ لِلْاذْقَانِ میں انتہائی تذلل کااظہار کیاگیاہے کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گرجاتے ہیں.تفسیر.اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ سے مراد اس جگہ مسلمان ہیں جن کوپہلے سے یعنی آیت کے نزول سے قبل علم
Page 449
مل چکا تھا اوروہ اسلام کی سچائی کے قائل ہوچکے ہیں.و ہ جانتے ہیں کہ آئندہ دنیا کی ترقی قرآن مجید سے ہوگی.اس جگہ اُوْتُواالْعِلْمَ سے اہل کتاب مراد نہیں ہوسکتے.کیونکہ وہی تو اس سورۃ میں سب سے اہم مخاطب ہیں.يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ.ذَقَنٌ.ٹھوڑی کوکہتے ہیں.اورٹھوڑی نیچے کی طرف ہوتی ہے.پس ٹھوڑی کے لئے گرنے یاٹھوڑی پر گرنے سے مرادنیچے کی طرف جھکنے یا سجدہ کرنے کے ہوتے ہیں.اظہار خشوع کے لئے اسلامی طریق کا فرق عیسائیوں سے اس آیت میں خشوع و خضوع کے اظہار کااسلامی طریق بتایا گیا ہے.بعض قومیں مثلاً عیسائی وغیرہ سجدہ کے موقعہ پر نیچے کو جھکتے ہیں.مگرمنہ کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں.چنانچہ عیسائیوں کی تصویروں میں جہاں پر حضرت مسیح یاحضرت مریم کوعبادت کی حالت میں دکھایا ہے.وہاں پر ان کامنہ آسمان کی طرف دکھایاگیاہے.وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ اوروہ کہتے ہیں (کہ )ہمارارب(ہرایک عیب سے )پاک ہے (اوریہ کہ )ہمارے رب کاوعد ہ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا۰۰۱۰۹ ضرور پوراہوکر رہنے والا ہے.تفسیر.اس آیت میں صاف ظاہر کردیا کہ اس سے پہلے مومنوں کے لئے ترقیات کے وعدے دیئے گئے ہیں اور’’اسراء‘‘ کا ذکر صرف ایک خبر ہی نہ تھا بلکہ مومنوں کی اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کاوعدہ تھا.سورۃ کے شروع میں بھی اسراء کے ذکر پر ’’سُبْحٰنَ الَّذِيْۤ اَسْرٰى ‘‘رکھا اوریہاں بھی ’’سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ ‘‘ فرماکر بتایا کہ اس مقام میں مسلمانوں کی ترقی اورکامیابی کاوعدہ کیاگیاہے.پھر سُبْحٰنَ کے لفظ سے یہ اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ مسلمان ضرو رکامیاب ہوں گے اور تم ضرورتباہ و برباد کئے جائو گے کیونکہ اگر ایسانہ ہو تو خدا تعالیٰ کی قدوسیت پرحرف آتاہے.وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًاؑ۰۰۱۱۰ اوروہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرجاتے ہیں.اوروہ (یعنی قرآن )ان کی فروتنی کو (اوربھی )بڑھاتاہے.
Page 450
تفسیر.اس میں مومن کے سجدہ کے وقت کی قلبی کیفیت بیان فرمائی ہے کہ وہ انابت کے اعلیٰ مقام پرہوتاہے اس کاسجدہ دکھاوے کانہیں ہوتا.بلکہ جبکہ و ہ سجدہ کررہاہوتاہے اس کے آنسوآپ ہی آپ بہنے لگ جاتے ہیں.پھر اس میں یہ صفت بھی پائی جاتی ہے کہ عبادت اسے متکبر نہیں بناتی.بلکہ ا س کاسجدہ کرنااسے خشوع وخضوع میں اوربڑھادیتاہے.قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ١ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ تو(انہیں )کہہ(کہ )تم(خدا تعالیٰ کو )اللہ(کہہ کر )پکارویارحمٰن(کہہ کر)جو (نام لے کر )بھی تم (اسے) الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ١ۚ وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ پکارو(پکارسکتے ہو)کیونکہ تمام (بہترسے )بہتر صفات اسی کی ہیں.اورتُواپنے دعائیہ الفاظ اونچی آواز سے نہ کہا کر بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا۰۰۱۱۱ اورنہ انہیں (بہت) آہستہ کہا کر.اوراس کے درمیان(درمیان)کوئی راہ اختیار (کیا )کر.حلّ لُغَات.لاتجھر.لَاتَجْھَرَجَھَرَ سے نہی کا صیغہ ہے.اور جَھَرَ الْکَلَامَ وَبِالْکَلَامِ کے معنے ہیں.اَعْلَنَہٗ.کسی بات کااعلان کیا.جَھَرَ اَلصَّوْتَ:اَعْلَاہُ.آواز کواونچاکیا (اقرب)پس وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا کے معنے ہوں گے کہ تواپنے دعائیہ الفاظ اونچی آواز سے نہ کہا کر اورنہ آہستہ.لاتُخافِتْ.لَاتُخَافِتْ خَافَتَ سے فعل نہی ہے اورخَفَتَ سے نکلا ہے.خَفَتَ اَوْ خَافَتَ بِکَلَامِہِ کے معنے ہیں.اَسَرَّ مَنْطِقَہٗ.پوشیدہ بات کی.خَفَتَ بِصَوْتِہِ :خَفَضَہٗ وَاَخْفَاہُ وَلَمْ یَرْ فَعْہُ بہت ہی آہستہ بولا.آواز کونیچا کیا.اوربلند نہ ہونے دیا(اقرب) تفسیر.سجدہ میں دعا کا طریق پہلی آیات میں چونکہ سجد ہ اورعبادت کا ذکر کیا گیاتھا (جس کی مسلمانوں سے ترقیات کے زمانہ میں امید کی جاتی تھی )ا ب سجدہ میں دعا کاطریق بیان فرماتا ہے کہ ان سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے اس کے وعدوں کے پوراہونے کے متعلق اوراپنی اصلاح کے متعلق اس طریق پر دعاکرو.جو ہم بتاتے ہیں.اس حکم کی تفصیل یہ ہے.
Page 451
مختلف صفات الٰہیہ کا تعلق دعا سے قرآن مجید میں اورحدیث میں مختلف دعائیں اوران کے مواقع کا ذکر ہے اس لئے فرماتا ہے کہ فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ہرکام کے لئے اس کے مناسب حال اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہوتاہے.اس کے مطابق دعاکیاکرو.جب تمہیں رحمانیت کی صفت کو جو ش دلانے کی ضرورت ہو توصفت الرحمٰن کو پیش کرکے دعاکرو.جب تمہیں رحیمیت.رزاقیت اوروہابیت کے متعلق کو ئی مشکل درپیش ہو تواللہ تعالیٰ کو ا س وقت اسی نام سے پکارو.کیونکہ سارے اچھے نام اسی کے ہیں.جیساموقعہ ہو ویسی ہی قسم کی صفت کے ساتھ دعاکرنی چاہیے.میراتجربہ ہے کہ اس طریق پر دعانہایت مؤثر ہوتی ہے.بعید نہیں کہ اس آیت میں یہود کے اسم اعظم والے دعویٰ کابھی جواب دیا گیا ہو.اوربتایا ہوکہ کسی ایک نام کو اسم اعظم کہنا غلطی ہے.حصول مقاصد کے لئے خدا تعالیٰ کے اس نام کو لینا چاہیے جوموقعہ کے مناسب ہو.اوراگر وہ نام ذہن میں نہ آئے تواللہ تعالیٰ کے سب نام ہی بڑے ہیں کسی نام کو لے کر دعاکرلو.اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھ کر دعاسن لے گا.وَ لَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا.صلوٰۃ کے معنے نماز کے بھی ہوتے ہیں.اوردعا کے بھی.اس جگہ چونکہ دعا کا ذکر ہے اس لئے دعاہی کے معنے زیادہ مناسب ہیں.فرمایا.اپنی دعابہت بلند آواز سے نہ مانگاکرو اورنہ ہی بالکل دھیمی بلکہ درمیا ن کاراستہ اختیارکرو.حدیث میں آتاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم چند صحابہ کے پاس سے گذرے توآپؐ نے دیکھا کہ و ہ پکارپکار کردعاکررہے تھے.آپ نے ان کو منع فرمایا اورکہا کہ تمہاراخدابہرہ نہیں ،اس قدراونچے پکارتے ہو و ہ توچیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے.قرآن مجید نے بالکل آہستہ دعاکرنے سے بھی منع کیا ہے.کیونکہ اس سے توجہ قائم نہیں رہتی.دعااس طرح کرنی چاہیے کہ انسان کو کلمات زبان سے نکلتے ہوئے محسوس ہوں تاکہ اس کی توجہ بھی قائم رہے.غرض دعابہت بلند آواز سے مانگنے سے تو خدا تعالیٰ کی شان کو مدنظر رکھتے ہوئے منع فرمایا ہے اورنہایت آہستہ دعامانگنے سے انسان کی کمزوری کو مدنظر رکھتے ہوئے منع فرمایا ہے.
Page 452
وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ اور(سب دنیا کوسناسنا کر)کہہ(کہ )کامل تعریف اللہ(تعالیٰ)کے لئے (ہی )مخصوص ہے جو نہ (تو)اولاد رکھتا شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ ہے اورنہ حکومت میں اس کاکوئی شریک ہے اورنہ (اس کے )عجز کی وجہ سے اس کاکوئی دوست (بنا)ہے.(بلکہ جو تَكْبِيْرًاؒ۰۰۱۱۲ بھی اس کادوست ہوتاہے اس سے مددلینے کے لئے ہوتاہے )اوراس کی خوب (اچھی طرح)بڑائی بیان کر.تفسیر.اس میں اسراء کے انجام کی خبر دی ہے یعنی و ہ خدااپنے اس وعد ہ کوضرو رپوراکرے گا.اوراسی واحد لاشریک خدا کی تعریف کے گیت گائے جائیں گے اگراس کاکوئی بیٹاہوتا جیساکہ بیت المقدس والوں کاخیال ہے تو مسلمانوںکو کس نے پوچھنا تھا ایسا ہی اگراس کے شریک ہوتے جیسا کہ مکے والے کہتے ہیں تومسلمانوں کوحکومت کو ن دیتایعنی یہ دونوں قومیں جو مشرک ہیں مسلمانوں کی دشمن تھیں اگرشرک صحیح ہوتا تومسلما ن دنیا میں ہرگز کامیاب نہ ہوسکتے.لیکن جب اس خدا نے باوجودانتہائی کمزوریوں کے مسلمانوں کو ان سب پر غالب کردیا تویقیناً سمجھا جائے گاکہ وہ خداواحد اورلاشریک ہے.مِنَ الذُّلِّ دوست دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک دوست جو رحم کی وجہ سے اوراحسان کرنے کے لئے بنایا جاتاہے ایسے دوست اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں یہ اس کی شان کے خلاف نہیں دوسرے و ہ دوست جو امداد اورموقعہ پر کام آنے کے لئے بنائے جاتے ہیں.ایسے دوست اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں.مسلمانوں کی ترقی شرک کی تردید ہے كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا کہہ کرسور ۃ کو ختم کیا گیاہے.اوراس میں گویا پھر اس امر کی طرف اشار ہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب پر غلبہ ملے گااورجس طر ح اہل مکہ پر غلبہ بتوں کے جھوٹے ہونے کی علامت ہو گااہل کتاب پر غلبہ ان لوگوں کے جھوٹاہونے کی دلیل ہوگا جومسیح ابن اللہ یاعزیرابن اللہ کہتے ہیں اوراس غلبہ کے ذریعہ سے خدائے واحد کی توحید تمام ملک میں پھیلادی جائے گی.اورخدا کابیٹاماننے والے یااس
Page 453
کاشریک قرار دینے والے سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی غلامی میں داخل کردیاجائے گا اور کمزور اورناتوان انسان کوطاقت بڑائی اورغلبہ دے کر ظاہر کیاجائے گاکہ وہ خداتمام طاقتوں سے بڑااوربلند ہے.اسی وجہ سے آخر میں فرمایا كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا.آئوہم بھی امتثال امر کے طور پر کہیں اللہ اکبر! اللہ اکبر !اللہ اکبر ! خ خ خ خ خ
Page 454
سُوْرَۃُ الْکَہْفِ مَکِّیَّةٌ سورہ کہف ۱؎ یہ سورۃ مکی ہے.وَھِیَ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ مِائَۃُ وَاِحْدٰی عَشَرَ ۃَ اٰیَۃً وَاِثْنَا عَشَرَ رُکُوْعًا اوربسم اللہ سمیت اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اوربارہ رکوع ہیں.یہ سورۃ مکی ہے ۱؎ ابن عباسؓ اورابن زبیر کے نزدیک یہ سورۃ سب کی سب مکی ہے (درمنثور)تمام مفسرین کابھی اس امر پر اتفاق معلوم ہوتاہے.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے بھی معلوم ہوتاہے کہ نہ صرف مکی ہے بلکہ ابتدائی ایام کی ہے.وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ،کہف،اورمریم ابتدائی سورتو ں سے ہیں اور میرے پرانے مال میں سے ہیں (بخاری کتاب التفسیر سورۃ بنی اسرائیل ).یہ سورۃ یکدم نازل ہوئی بعض کے نزدیک یہ سورۃ ان سورتوںمیں سے ہے جو یکدم نازل ہوئی ہیں.دیلمی نے انسؓ سے یہی روایت کی ہے کہ یہ سور ۃ یکدم نازل ہوئی تھی اورسترہزارفرشتہ ساتھ تھا اورا س کی خاص طورپر حفاظت کی گئی تھی(فردوس الاخبار از دیلمی حدیث نمبر ۷۰۷۰).سورۃ کے یکدم نازل ہونے اور اس کے ساتھ فرشتوں کے نزول کا مطلب ان روایات کایہ مطلب نہیں کہ بعض سورتوں کی حفاظت کم ہوئی ہے اوربعض کی زیادہ.کیونکہ اگریہ تسلیم کیا جائے تویہ بھی مانناپڑے گاکہ بعض سورتوں کامحفو ظ ہونا زیادہ یقینی ہے اوربعض کاکم.لیکن یہ امر بالبداہت غلط ہے پس جہاں جہاں حدیثوں میں آتاہے کہ فلاں سورۃ کی حفاظت کے لئے اتنے فرشتے اترے.اس سے نزول کے وقت کی حفاظت مراد نہیں.بلکہ نزول کے بعدکی حفاظت مراد ہوتی ہے.اوروہ اس طرح کہ ہرسورۃ کسی خاص مضمون کے بارہ میں ہوتی ہے اوربعض دفعہ اس میں پیشگوئیاں ہوتی ہیں جن کے پوراہونے پر اس سورۃ کی سچائی کاانحصار ہوتاہے.یہ پیشگوئیاں بعض دفعہ طبعی تغیرات کے متعلق ہوتی ہیں اوربعض دفعہ انسانی اعمال کے متعلق.انسانی اعمال کے متعلق جوپیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہیں کہ جن کے عذاب کی ان پیشگوئیوں میں خبرہو.وہ اس عذاب کو ٹالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور چونکہ پیشگوئیاں بالعموم غیر معمولی طورپر مخالف حالات میں کی جاتی ہیں.اس لئے دنیوی سامانوں کے لحاظ سے ان کاپورا ہونا بظاہرناممکن یاغیراغلب نظر آتاہے اوراسی وقت ان کے پوراہونے کی کوئی صورت پیداہوسکتی ہے.جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امدادکاانتظام کیا جائے.پس جس سور ۃ میں اس قسم کی
Page 475
تفسیر.فرمایاوہ دنیا کاسامان تو ایک عارضی چیز اورعارضی سامان ہے.حقیقی نہیں.صر ف قومی مقابلہ کاایک ذریعہ خدا تعالیٰ نے بنایاہے تابنی نوع انسان کی خدمت کرکے ثواب حاصل کریں.لیکن مسیحی لوگ اس غرض کو پوری نہ کریں گے خداکے پیداکئے ہوئے سامانوں کی جستجوتوکریں گے لیکن ان کو حسن عمل کاذریعہ نہ بنائیں گے اورلڑائی جھگڑے کاذریعہ بنالیں گے.پس چونکہ ہمار امقصد توان اشیاء کے پیداکرنے سے دنیا کوزینت دینا ہے چونکہ وہ مقصد ان کی تحقیقاتوں اورایجادوں سے پورانہ ہوگا.ہم ان کے کام کومٹادیں گے غر ض اس جگہ سب دنیا کی تباہی مراد نہیں بلکہ ان کاموں کی تباہی مراد ہے جواللہ کابیٹابنانے والی قوم کرے گی.اس آیت کے الفاظ میں نہایت لطیف طورپر ایک تمثیل کی طرف جواس سور ۃ میں آگے چل کربیان ہوئی ہے اشارہ فرمایاگیاہے اوروہ اشار ہ صَعِيْدًا جُرُزًاکے الفاظ میں ہے.صعید کے معنے اس زمین کے ہوتے ہیں جس میں سے درخت وغیر ہ کٹ جائیں.چنانچہ عرب کامحاورہ ہے صَارَتِ الْحَدِیْقَۃُ صَعِیْدًا باغ اُجڑ گیا اس کے درخت فناہوگئے.اور جرز کے معنے بھی اس زمین کے ہوتے ہیں جس کی سبزی تباہ ہوگئی ہو آگے چل کرجہاں دوباغوں کی تمثیل دی گئی ہے (کہف ع ۵)وہاںبھی متکبر باغوںوالے کو اس کاناصح بھائی کہتاہے کہ تو تکبر نہ کر ایسانہ ہو کہ آسمانی عذاب نازل ہوکر تیرے باغوں کو صعیدًا زَلَـقًابنادے.صَعِیْدًا کالفظ تووہی ہے جویہاں استعمال ہواہے.جُرُزًاکی جگہ وہا ںزَلَقًا کالفظ رکھا گیا ہے اوراس کے معنے بھی یہی ہیں کہ جہاں کوئی کھیتی نہ ہو.عرب کہتے ہیں کہ اَرْضٌ زَلَقٌ ایسی زمین جس پر کوئی کھیتی نہ ہو.پس اس آیت سے اس طرف اشار ہ ہے کہ آگے جو تمثیل بیان کی گئی ہے مسیحی قوم بھی اس میں شامل ہے اوراللہ تعالیٰ ان کے لگائے ہوئے باغوں کوتباہ کردے گا.اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ١ۙ كَانُوْا مِنْ کیا توسمجھتا ہے کہ کہف اوررقیم والے (لوگ)ہمارے نشانوں میں سے کوئی اچنبھا (نشان )تھے اٰيٰتِنَا عَجَبًا۰۰۱۰ (جن کی نظیر پھرکبھی نہ پائی جاسکتی ہو ).حلّ لغات.الکھف.اَلْکَھْفُ کَالْبَیْتِ الْمَنْقُوْرِ فی الْجَبَلِ.گھر کی شکل پر پہاڑ میں کھود کر بنایا
Page 476
ہوامکان.اس کی جمع کُھُوْ فٌ آتی ہے.غار اور کہف میں یہ فرق ہے کہ کہف وسیع ہوتی ہے اورغار تنگ.اَلْکَھْفُ اَیْضًا الْوَزَرُ.حفاظت کی جگہ.اَلْمَلْجَا ءُ.پناہ کی جگہ (اقرب) رقیم رَقِیْمٌ رَقَمَ(یَرْقُمُ رَقْمًا)کے معنے ہیں کَتَبَہٗ.اس کو لکھا.رَقَمَ الْکِتَا بَ.اَعْجَمَہُ وَبَیَّنَہٗ.کسی کتاب یا خط کے الفاظ کو واضح طور پر لکھا.رَقَمَ الثَّوْبَ.خَطَّطَہٗ وَاَعْلَمَہُ.اس پر لکیریں ڈالیں اورشاندار کیا.کسی چیز پر تصویر بنانا.لکھنا.نقش بنانا.اَلرَّقِیْمُ.الْکِتَابُ.اَلْمَرْقُوْمُ.لکھی ہوئی چیز.اَصْحَابُ الرَّقِیْمِ کے معنے ہوں گے.نقش یا تصویریں بنانے والے لوگ.مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر یالوہے پر کھو دنے والے لوگ (تفسیر ابن جریر و اقرب).تواس لحاظ سے یہ معنی ہوں گے پتھروں پر یاکاغذوں پر لکھنے والے یا نقش ونگار کرنے والے یاتصویریں بنانے والے یاکھودنے والے.رَقِیْمٌ بمعنے مَرْقُوْمٌ بھی ہوسکتا ہے اس لحاظ سے اصحاب الرقیم کے معنے ہوں گے جن کے پاس لکھی ہوئی چیز یں ہو ں.یعنی کتابیں یا ساما ن جن پرنام لکھاہواہو یاکتبوں والے وغیر ہ وغیر ہ.العَجَبُ اَلْعَجَبُ (۱)جب کوئی ایساامر پیش آئے کہ اس کے ماننے میں طبیعت کو انقباض اور انکار ہو.تواس انکار کی حالت کو عجب کہتے ہیں (۲) پیش آمد ہ امر کے پسند کرنے کوبھی عجب کہتے ہیں (۳)اس حالت رعب کو بھی عجب کہتے ہیں جوانسان پر کسی چیز کو بہت ہی بڑا سمجھنے کے وقت طاری ہوتی ہے.(اقرب)تفصیل کے لئے دیکو سورہ یونس آیت نمبر ۳.اَلْعَجَبُ.اِنْکَارُمَا یَرِدُ عَلَیْکَ یعنے جب کوئی ایسا امر پیش آئے کہ اس کے ماننے میں طبیعت کو انقباض اور انکار ہو تو اس حالت انکار کو عجب کہتے ہیں.اِسْتِطْرَافُہُ.پیش آمدہ امر کو پسند کرنے کو بھی عجب کہتے ہیں.رَوْعَۃٌ تَعْتَرِی الْاِنْسَانَ عِنْدَ اِسْتِعْظَامِ الشَّیْءِ.یعنی اس حالت رعب کو بھی عجب کہتے ہیں جو انسان پر کسی چیز کو بہت ہی بڑا سمجھنے کے وقت طاری ہوتی ہے.وَمِنَ اللہِ : الرِّضَی اور جب اللہ کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا جاوے تو اس کے معنی پسندیدگی کے ہوتے ہیں.(اقرب) تفسیر.کیا لطیفہ ہے بلکہ رونے کا مقام ہے کہ خدا تعالیٰ توکہتاہے کہ اصحا ب کہف کو ئی عجوبہ چیز نہ تھے بلکہ اورآیتوں کی طرح یہ بھی ایک آیت ہی تھے.مگر ہمار ے مسلمان اس کوایک عجوبہ بنارہے ہیں (اصحاب کہف کی تفصیل کے لئے دیکھو اگلی آیات)
Page 477
اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَاۤ جب وہ (چند )نوجوان وسیع غار میں پناہ گزین ہوئے اور(دعاکرتے ہوئے )انہوں نے کہا (کہ )اے ہمارے اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّ هَيِّئْ لَنَا مِنْ رب ہمیں اپنے حضور سے (خاص )رحمت عطاکر.اورہمارے لئے ہمارے(اس )معاملہ میں اَمْرِنَا رَشَدًا۰۰۱۱ درست روی کاسامان مہیا کر.حلّ لُغَات.اَوَی.اَوَی اِلٰی مَنْزِلِہِ وَمَنْزِلَہُ کے معنے ہیں نَزَلَ بِہ لَیْلًااَوْنَھَارًا وہ اپنے مقام میں رات کو یادن کو اترا.(اقرب) الفِتْیَۃُ.اَلْفِتْیَۃُ اَلْفَتیٰ کی جمع ہے اوراَلْفَتٰی کے معنے ہیں اَلشَّابُ الْحَدَثُ.نوجوان.اَلسَّخِیُّ الْکَرِیْمُ.فیاض اورسخی (اقرب) الرّحمۃ.الرَّحْمَۃُ رِقَّۃُ الْقَلْبِ وَالْاِنعِطَافِ یقْتَضِی التَّفَضُّلَ وَالْاِحْسَانَ وَالْمَغْفِرَۃَ.رقت قلب جو ترس احسان اوربخشش کی مقتضی ہو تی ہے.نیز رحمت کے معنے مغفر ت کے بھی ہوتے ہیں (اقرب) تفسیر.رشدکے معنی ہدایت کے ہیں مگررَشد زیادہ تر دینی امورمیں اوررُشد دینی اوردنیوی امور کی ہدایت کے لئے آتاہے (اقرب).پس دعا کامطلب یہ ہواکہ اے اللہ ہمارے لئے اس معاملہ میں آزادی اور کامیابی کارستہ نکال.فَضَرَبْنَا عَلٰۤى اٰذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًاۙ۰۰۱۲ جس پر ہم نے اس وسیع غار میں چند گنتی کے سالوں کے لئے انہیں (بیرونی حالات کے )سننے سے محروم کردیا.حلّ لُغَات.ضَرَبَ عَلٰی اُذْنِہٖ.مَنَعَہُ اَنْ یَسْمَعَ.اس کو سننے سے روک دیا (اقرب) تفسیر.ضَرَبْنَا عَلٰۤى اٰذَانِهِمْ کے معنے ہیں ہم نے ان کو سننے سے روک دیا.یعنی کچھ سال تک ان کو کہف
Page 478
میں رکھ کر باقی لوگوں کے حال سے ناواقف رکھا.ان کومعلوم نہ ہوتاتھا کہ زمانہ کاکیاحال ہے.(اصحاب کہف کون تھے اس کے لئے دیکھو اگلی آیت ) ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْۤا پھر ہم نے انہیں اٹھایاتاکہ ہم جان لیں کہ جتنی مدت وہ (وہاں )ٹھہرے رہے تھے اسے دونوں گروہو ںمیں سے اَمَدًاؒ۰۰۱۳ زیادہ محفوظ رکھنے والا کون ساگروہ ہے.حلّ لُغَات.بَعَثْنَا.بَعَثْنَابَعَثَ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے.اوربَعَثَ کے لئے دیکھو حجر ۳۲.یُبْعَثُوْنَ بَعَثَ سے جمع مذکر غائب مجہول کاصیغہ ہے.اوربَعَثَہٗ(یَبْعَثُ بَعْثًا)کے معنے ہیں اَرْسَلَہٗ اس کو بھیجا.بَعَثَہُ بَعْثًا: اَثَارہٗ وَھَیَّجَہٗ.اس کو اُٹھایااورجوش دلایا.بَعَثَ اللہُ الْمَوْتٰی:اَحْیَاھُمْ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا.بَعَثَہٗ عَلی الشَّیْءِ حَمَلَہٗ عَلٰی فِعْلِہِ.اس کو کسی کام کے کرنے پر اُکسایا.اَلْبَعْثُ.النَّشْرُ اُٹھانا.(اقرب) الحِزْبَیْنِ.اَلْحِزْبَیْنِ اَلْحِزْبُ سے تثنیہ کاصیغہ ہے اورالحزب کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر۳۶.اَلْحِزْبُ کے معنے ہیں اَلطَّائِفَۃُ.گروہ.جَمَاعَۃُ النَّاسِ لوگوں کی جماعت.جُنْدُ الرَّجُلِ وَاَصْحَابُہُ الَّذِیْنَ عَلٰی رَأیِہٖ.ایسے دوست اور ساتھی جو ہم خیال اور ہم رائے ہو.النَّصِیْبُ.حصہ.کُلُّ قَوْمٍ تَشَاکَلَتْ قُلُوْبُھُمْ وَاَعْمَالُھُمْ فَھُمْ اَحْزَابٌ وَاِنْ لَمْ یَلِقْ بَعْضُہُمْ بَعْضًا.تمام وہ لوگ جن کے اعمال اور دل آپس میں مشابہ ہوں.اگرچہ وہ آپس میں ملے نہ ہوں.احزاب کہلاتے ہیں.(اقرب) الامد.اَلْاَمَدُکے معنے ہیں اَلْغَایَۃُ.آخری حد غایت و انتہاء (اقرب).اَلْاَمَدُوَالْاَبَدُیَتَقَارَبَانِ لٰکِنِ الْاَبَدُ عِبَارَۃٌ عَنْ مُدَّۃِالزَّمَانِ الَّتِیْ لَیْسَ لَھَا حَدٌّ مَحْدُوْدٌ وَلَایَتَقَیّدُ.وَالْاَمَدُ مُدَّۃٌ لَھَاحَدٌّ مَجْھُوْلٌ.اَمَد اورابَد تقریباًایک جیسے ہی معنے رکھتے ہیں لیکن ابد اس زمانہ کو کہتے ہیں جوغیر محدود ہو.اورامد اس مدت کو کہتے ہیں جس کی انتہاء معلوم نہ ہو.والْفَرْقُ بَیْنَ الزَّمَانِ وَالْاَمَدِ أَنَّ الْاَمَدَ یُقَالُ بِاِعْتِبَارِالْغَایَۃِ وَالزَّمَانُ عَامٌ فِی
Page 479
الْمَبْدَإِ وَالْغَایَۃِ.وَلِذٰلِکَ قَالَ بَعْضُھُمْ اَلْمَدٰی وَالْاَمَدُ یَتَقَارَبَا نِ.اورزمان اورامد کے لفظ کے درمیان یہ فرق ہے کہ امد کالفظ انتہا ء کااعتبا رکرتے ہوئے بولاجاتاہے.اورزمانہ عام ہے.وہ مبداء پر بھی اورانتہاء پر بھی بولاجاتا ہے.اس فرق کے پیش نظر بعض نے مدی اورامد کو متقارب المعنی قراردیاہے (مفردات) تفسیر.اصحاب کہف کون تھے کہاں تھے؟ اصحاب کہف کون تھے ؟ کہاں تھے اوران کے حالات کیا ہیں؟یہ ایک نہایت اہم سوال ہے جو صدیوں سے مفسرین کے دلوں میں ہیجان پیداکر تاچلاآیا ہے.میں اس سوال کوحل کرنے کے لئے سب سے پہلے بعض روایات بیان کرتاہوں جواصحا ب کہف کے متعلق پرانے مفسرو ں نے بیان کی ہیں.اصحاب کہف کے حالات (۱)مشہور مؤرخ ابن اسحا ق اوربعض دوسرے مصنفوں نے یہ لکھا ہے کہ جب مسیحیوں میں شر ک پیداہوگیا.بتوں کی پوجا اور ان کے لئے قربانی شروع ہوگئی توان میں سے کچھ لوگوںکو جوموحد تھے یہ امر برالگا.اس زمانہ میں دقیانوس نامی مسیحی بادشاہ تھا.بعض روایات میں اس کانام دقیوس آیا ہے.یہ بادشاہ موحد نصاریٰ کو قتل کرتا تھا انہی ایا م میں موحد نصاریٰ میں سے کچھ امراء نوجوانوں کو جوافیوس یا بعض روایا ت میں لکھا ہے کہ طرسوس کے رہنے والے تھے شاہی سپاہیوں نے پکڑ لیااوربادشاہ کے سامنے پیش کیا.ا س نے انہیں بتوں کو سجدہ نہ کر نے پر ڈانٹا.مگر وہ توحید پر قائم رہے.اس پر بادشاہ نے ان کوکچھ مہلت دی کہ اس عرصہ میں سوچ لو.انہوں نے اس موقعہ کو غنیمت سمجھا اوروہاں سے بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے جس کانام منجلوس تھا.باقی توعبادت میں مشغول ہوگئے اوراپنے میں سے ایک کو جس کانام یملیخاتھا.سوداسلف لانے پرمقر کردیا.و ہ بھیس بدل کر شہر میں جاتااورسودالے آتا.ایک دن اسے معلوم ہواکہ بادشاہ جو باہرکسی مہم پر گیا ہواتھا واپس آگیا ہے اوراس نے ان نوجوانوں کو پھر طلب کیا ہے.و ہ روتاہواآیا اورسب کو اس کی خبر دی.انہوں نے خوب روروکردعائیں کرنی شروع کیں.جب دعائیں ختم ہوئیں تواللہ تعالیٰ نے ان کو سلادیا.ان کاسامان ا ن کے سرہانے پڑاتھا اورکتادہلیز پرتھا.بادشاہ نے ان کاپتہ لے کر ان کا پیچھا کیا.مگرجب غار میں بعض لوگوں کوبھیجا توکوئی غار میں نہ جاسکا.اس پر ایک مصاحب نے کہا کہ اے بادشاہ آپ کی غرض ان کومار نا ہی توہے.آپ اس غار کے دروازہ پر دیوار کھینچوادیں آپ ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے.بادشا ہ نے اس کے مشورہ کے مطابق دیوار کھنچوادی.اس کے بعد وہ کچھ گذراجو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیا ن فرمایا ہے.(روح المعانی زیر آیت ھذابحوالہ ابن اسحاق) (۲)بعض نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح ؑ کے ایک حواری تھے وہ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے شہر میں پہنچے جس کا
Page 480
بادشاہ بت پرست تھا.اوراس نے حکم دے رکھا تھا کہ جوشہر میں داخل ہوپہلے درواز ہ پرنصب کئے ہوئے بت کو سجدہ کرے انہوں نے ایسانہ کیا.اورشہر کے باہر ایک حمام میں ٹھیر گئے اور وہیں تبلیغ شروع کردی.جس کی وجہ سے کئی لوگ ان کے ہم خیا ل ہوگئے.ایک دن بادشاہ کالڑکا ایک فاحشہ کو لے کر حما م کرنے کے لئے آیا.اس حواری نے اسے نصیحت کی.و ہ اس دن رک گیا.دوسری دفعہ پھر آیا توانہوں نے اسے ڈانٹا اس نے بات نہ مانی اوراس فاحشہ سمیت حمام میں چلا گیا.صبح کے وقت و ہ مردہ پایا گیا.بادشاہ کو لوگوں نے کہا کہ حمام والے نے ماردیا ہے.بادشاہ نے تحقیق شروع کی.حمام والا بھاگ گیااوراس کے سب دوست بھی.کچھ نوجوا ن جو مسیحی ہوچکے تھے وہ بھی ڈر کر بھاگے اورایک زمیندار کے پاس جوان کادوست تھا گئے وہ بھی ان کا ہم خیال تھا.وہ ان کو لے کر ایک غار میں جا چھپا.بادشاہ کو علم ہوا.تو و ہ پکڑنے گیا.اس سے آگے وہی لوگوں کے ڈرنے اوربادشا ہ کے دیوار بنانے کاواقعہ ہے.(اَخرجَہٗ عبدالرزاق وابن المنذر عن وھب بن منبہ.روح المعانی زیر آیت ھذا) ابن المنذر اورابن ابی شیبہ اورابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ میں حضرت معاویہؓ کے ساتھ رومیوں کے مقابلہ پر جہاد کے لئے گیا تھا.اس سفر میں ہم نے اصحاب کہف کی غار دیکھی.معاویہؓ نے کچھ لوگ اس غار کو دیکھنے کے لئے بھیجے مگر آندھی آگئی اور وہ لو گ اند ر نہ جاسکے.(درمنثور زیر آیت ھذا) ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب کہف کی ہڈیا ں دیکھیں.و ہ تین سو سال کی پرانی تھیں (درمنثور زیر آیت ھذا) اصحاب کہف کے متعلق تفاسیر کے واقعات ان کے انجام کے متعلق مندرجہ ذیل روایات کتب تفسیر میں بیان کی گئی ہیں.(۱)ایک لمبے عرصہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا پھر جگادیا.انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو کھانا لینے بھیجا.اس نے دوکاندار کوجوسکہ دیا.اسے دیکھ کروہ حیران رہ گیاکیونکہ وہ سکہ پراناتھا.ا س نے اَوردکانداروں کودکھایا.سب اس سکہ کو دیکھ کرحیران ہو ئے کہ یہ کس ملک کاسکہ ہے.آخر بادشاہ تک معاملہ پہنچا جس کانام نندوسیس تھا.بادشاہ نے اس نوجوان سے سب واقعہ سنا اوراس کے ساتھ غار تک آیا.وہاں سب اصحاب کہف سے ملا اوران سے بغلگیر ہوا.کچھ دیر باتیں ہو ئیں.پھر اصحاب کہف نے اس کونصائح کیں اور لیٹ گئے اوراسی وقت مر گئے (روح المعانی وابن کثیر سورۃ الکہف زیر آیت و کذالک اعثرنا علیہم) (۲)بعض دوسری روایات میں آتاہے کہ جب لوگ غار پر پہنچے تووہ لوگ اسی وقت مرگئے.اوروہ ان کو زندہ نہ دیکھ سکے.اورجو کھانالینے گیاتھا وہ بھی وہاں پہنچ کر مرگیا.(عبدالرزاق وابن ابی حاتم عن عکر مۃؓ درمثورزیر آیت ھذا)
Page 481
دقیس والا واقعہ مسیحی کتب میں بھی لکھا ہواہے.مشہورانگریز مؤرخ گبن اپنی کتاب ’’رومن حکومت کی ترقی اورتباہی ‘‘میں لکھتاہے کہ ایک کہانی سات سونے والوں کے متعلق طورس کے پادری گریگوری نے لکھی ہے جسے میں لکھ دینا ضروری سمجھتاہوں.یہ کہانی شامی مسیحیوں میں مشہورتھی.اورا ن کی کتب سے گریگوری نے نقل کی ہے.گبن نے آگے جوکہانی نقل کی ہے.وہ ابن اسحاق کی روایت سے بہت ملتی ہے.اس میں لکھاہے کہ دقیس بادشاہ کے وقت یہی افسیس شہر کے چند امراء نوجوان جو مسیحی تھے انہوں نے مسیحیوں پر باد شاہ کاظلم دیکھ کر اپنے آپ کو ایک غار میں چھپادیا.بادشاہ نے غار کامنہ بندکروادیا.ایک سواسی سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا ایڈولیس جس کے پاس وہ علاقہ تھا اس کے غلاموں نے کسی ضرورت کے لئے غار کے منہ پرسے پتھر ہٹائے اورسورج کی شعاع اندر جانے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کردیا.و ہ جاگے توسمجھے کہ چند گھنٹے ہم سوئے ہیں.ان کوبھوک لگی توانہوں نے اپنے ایک ساتھی جیمبلیکس کو خوراک لینے بھجوایا.اس نے شہر کوبدلاہواپایا اوردروازہ پر صلیب دیکھی تواس کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی.نان پز کو جب اس نے سکہ دیا تواس کے لباس اورعجیب سکہ کودیکھ کر وہ حیران رہ گیا.اوریہ سمجھ کر کہ اسے کوئی خزانہ ملاہے اسے قاضی کے سامنے پیش کیا.جب انہوں نے واقعہ سنا توبادشاہ تھیو ڈوسیس اورسب امراء مل کر غار پر گئے.جہاں اصحاب کہف نے انہیں برکت دی اپنا قصہ سنایا اورفوت ہوگئے.(جلد او ل ص ۱۹۷) علامہ ابوحیان بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ سپین میںایک جگہ لوشاہے اس میں ایک غا رہے وہاں اصحاب کہف کی لاشیں بتائی جاتی ہیں اوراس میں ان کاکتابھی ہے.ابن ابی عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے.چار پانچ سوسال سے وہاں ان کی لاشیں پڑی ہیں(بحر محیط)اسی طرح و ہ لکھتے ہیںکہ غرناطہ کے پاس ایک اجڑاہواشہر ہے.جسے دقیو س کاشہر کہتے ہیں جو بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہواہے.اس میں عجیب عجیب قبریں ہیں.مفسرین نے اصحاب کہف کے نام بھی لکھے ہیں.چنانچہ ابن عباسؓ سے مروی ہے وہ یہ نام بتاتے ہیں.میکسل مینا ،تملیخا،مرطونس ،کشطونس ،بیرونس،ویلنموس ،بطونس اورقایوس.(ابن کثیرزیر آیت کہف :۲۲) اصحاب الرقیم کے متعلق تفاسیر کے واقعات رقیم کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں بعض کہتے ہیں کہ تانبے اورپتھر کی لوح پر ان کے نام لکھے تھے.اس لئے ان کانام رقیم ہوگیا.بعض کے نزدیک ان کے شہرکانام رقیم تھا.بعض کے نزدیک درہمو ں کانام تھا.اوربعض کہتے ہیں کہ ان کے کتے کا نام تھا.اوربعض کہتے ہیں کہ ان کی شریعت کانام تھا.اوربعض کے نزدیک ان کی وادی کانام تھا.اوربعض کے نزدیک پہاڑ کانام تھا.جس پر وہ غار تھی(قرطبی زیر آیت ان اصحاب الکہف...).
Page 482
ان روایا ت سے جو مسلمانوں کی کتب اور مسیحیوں کی کتب میں آئی ہیں یہ بات توثابت ہوجاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے اصحاب کہف کے قصے سے ملتے ہوئے واقعات لوگوں میں مشہور تھے.لیکن ان میں اس قدر اختلاف تھا کہ جیساکہ قرآن کریم فرماتا ہے ان پر اعتبار نہیں کیاجاسکتا.کیونکہ جھوٹ سچ ان میں ملاہواتھا.ان روایات کے علاوہ مفسرین نے ایسی بہت سی روایات بھی لکھی ہیں جن میں کتے کے حالات بیان کئے گئے ہیں.یہاںتک کہ کہا گیا ہے کہ جنت میںصرف دوحیوان ہوں گے ایک اصحاب کہف کاکتا اورایک بلعم کاگدھا.صاحب فتح البیان اس قسم کی بعض روایات نقل کرکے لکھتے ہیں لَااَدْرِیْ اَیَّ تَعَلُّقٍ لِھٰذَالتَّدْقِیْقِ وَالتَّحْقِیْقِ بِتَفْسِیْرِ الْکِتَابِ الْعَزِیْزِ وَمَاالَّذِیْ حَمَلَھُمْ عَلٰی ھٰذَا الْفُضُوْلِ الَّذِیْ لَامُسْتَنَدلَہٗ فِی السَّمْعِ وَلَافِی الْعَقْلِ (زیر آیت وتحسبہم ایقاظا و ھم...)یعنی میں نہیں سمجھتا کہ اس نام نہادتدقیق اور تحقیق کا تعلق قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ کیا ہے.اور ان مفسرین کو ان لغویا ت کے نقل کی طرف جن کا نہ کوئی عقلی ثبوت ہے نہ نقلی.کیوں رغبت ہوئی ہے.حضرت خلیفۃ المسیح الاول ؓ کی تحقیقات اصحاب کہف کے متعلق سابق مفسرین کے خیالات لکھنے کے بعد میں استاذی المکرم حضرت مولوی نورالدین خلیفہ اول جماعت احمدیہ ؐ کی تحقیق اس بارہ میں لکھتا ہوں.آپ کا خیال تھا کہ اصحاب کہف ابتدائی زمانہ کے مسیحیوں میں سے ایک موحد جماعت تھی.ان لوگوںنے شرک کی اشاعت سے ڈرکر کسی دوسرے ملک کاسفر کیا.اور وہاں مدتوں تک گمنامی میں پڑے رہے.آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی دی اور سب دنیا میں پھیلادیا.آپ کاخیال تھا کہ اس واقعہ میں یوسف آرمیتیا کے ایک سفر کی طرف اشارہ ہے جب کہ وہ اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر انگلستان چلے گئے تھے.وہاں انہوں نے پہلے مسیحی گرجا کی بنیاد رکھی (حقائق الفرقان زیر آیت اذ اوی الفتیۃ...).آپ کااشارہ اس روایت کی طرف ہے جوانگلستان میں صدیوں سے مشہور چلی آتی ہے.اور وہ یہ ہے کہ فلپ حواری نے یوسف آرمیتیا اور چند اورلوگوں کو انگلستان تبلیغ کے لئے بھجوایاتھا.وہاں انہوں نے GLOSTONBURYکے مقام پر ایک گرجابنایا اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کی(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ GLOSTONBURY) یہ قصہ’’ گلاسٹبنری کے گرجا کی قدامت‘‘ نامی کتاب میں مذکور ہے جوولیم نامی ایک شخص نے جو مالمس بری MALES BURY کاباشندہ تھا گیارہ سو پچیس عیسوی میں لکھا تھا.لیکن اس کے اس نسخہ میں جو
Page 483
اس نے خود لکھا اس واقعہ کا ذکر نہیں بلکہ یہ لکھا ہے کہ معتبر روایات سے معلوم ہوتاہے کہ انگلستا ن کے ایک بادشاہ لوسیئس (LUCUIS)کے کہنے پر پوپ نے ۱۶۶ ء میں ایک تبلیغی مشن انگلستان بھجوایاتھا جس نے یہ گرجا بنایا.ساتھ ہی ا س میں یہ بھی لکھاہے کہ ایک روایت اس گرجے کو اس سے بھی پہلے کابتاتی ہے.مگرمیںاس روایت کی تصدیق نہیں کرسکتا.ولیم کے مرنے کے بعد اس کی ایک کتاب کو دوبار ہ لکھوایاگیاتواس میں اوپر والاواقعہ درج کردیاگیا.گویایہ واقعہ ولیم کے بعداس کتا ب میں کسی اورنے لکھ دیاہے اوراس کی سند ا س نے کوئی نہیں دی.یہ جوکہف کالفظ قرآن کریم میں آتاہے ا س کے متعلق حضرت مولوی صاحب ؓ کاخیال تھا کہ اس سے مراد وہ (CAPE)ہے جوگلاسٹنبری کے پاس ساحل پر ہے جہاں تک کیپ کے لفظ کاتعلق ہے میرے نزدیک آپ کی رائے درست نہیں کیونکہ کیپ انگریزی کا لفظ فرانسیسی لفظCAP اورلاطینی CAPUTE سے بناہے جن کے معنے سرکے ہیں.اورخشکی کاایک حصہ جس کی نوک سمندرمیںآگے نکلی ہوئی ہو اسے کیپ (CAPE )کہتے ہیں.لیکن عربی لفظ کہف کے معنے وسیع غار کے ہیں.جو پہاڑی جگہ پر ہو یا پتھریلی زمین میں ہواوراسے کیپ سے جسے عربی جغرافیہ نویس رأس کے لفظ سے یاد کرتے ہیں.(جیسے ہندوستان کی ایک کیپ کانام رأس کماری ہے )دورکابھی کوئی تعلق نہیں.میرے نزدیک جس حد تک اصحاب کہف کے واقعہ کاتعلق یوسف آرمیتیا کے سفر سے ہے.میں اس کے متعلق بھی آپ کی تحقیق سے متفق نہیں.کیونکہ یوسف آرمیتیا کایہ سفر محض کہانی کی طورپر انگلستان میں مشہور رہاہے.اور سوا گیارہ سوسال بعد مسیح اس کا ذکر پہلی دفعہ ولیم کی کتاب میں ملتاہے اوروہ بھی ایک نامعلوم شخص نے اس کی موت کے بعد اس کتاب میں لکھ دیاہے.ایسے اہم امور کے متعلق تو ایک صد ی کی خاموشی بھی شبہ ڈال دیتی ہے.کجا یہ کہ ایک ہزار سال تک دنیا میں اس بار ہ میں کوئی روایت نہ ہو اورہزار سال کے بعد جاکر یہ روایت لکھی جائے.اگر آج کوئی شخص ایک نئی روایت جو کتب احادیث اورتاریخ میں موجود نہ ہو.لوگوں کی زبانی روایات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرے تو ایک شخص بھی اسے تسلیم کرنے کو تیارنہیں ہوگا.جب تک کہ کوئی ایسے تاریخی شواہد اس کی تائید میں نہ ملیں جواس واقعہ کو دوسرے ثابت شد ہ واقعات کی کڑی میں اس طرح پرودیں کہ انکار کی گنجائش نہ رہے.نیز اہل انگلستان جن کو اس قسم کی روایات پر فخر ہونا چاہیے اورایسی جھوٹی روایتوںکو بھی سچا بنا نا ا ن کے فائدہ کا موجب ہے وہ بھی تحقیق کرکے ان امو رکوغلط قراردے چکے ہیں.چنانچہ ولیم آف مالمسبری کے بعد اس گرجا کے قدیم کاغذات ملے ہیں جن کوپڑھ کر یہ نتیجہ نکالاگیاہے کہ یہ گرجا اس وقت سے زیادہ سے زیادہ تین ساڑھے تین
Page 484
سوسال پہلے بنا تھا.یعنی اس کی تعمیر کا وقت زیادہ سے زیادہ آٹھویں صدی مسیحی کے آخرمیں تجویز کیا جاسکتا ہے اوران کاغذات میں بھی اس روایت کاکوئی ذکر نہیں.اس لئے تحقیقات کے بعد انگریز مؤرخو ں نے لکھا ہے کہ ’’بہرحال یہ تاریخی واقعہ نہیں ہاںایک شاعرانہ خیال ضرور ہے‘‘(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکازیر لفظ Joseph do qrimathea) ان معمولی اختلافات کے اظہار کے بعد جو صر ف افراد اور ابتدائی مقام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں.میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جہاں تک اصحاب کہف کا تعلق گذرے ہوئے واقعات سے ہے.ان کے بارہ میں حضرت مولوی صاحب ؓ کی تحقیق ایک ایسی شمع ہدایت ہے جس کی قیمت کا انداز ہ نہیں لگایا جاسکتا.او ر بغیر اس روشنی کے جو انہوں نے اس مضمون پر ڈالی ہے یہ حصہ قرآن کریم کا تاریخی طورپر حل نہیں ہوسکتا تھا.فجزاہ اللہ احسن الجزاء اصحاب کہف کے واقعات میں حضرت مسیح موعود کے لئے پیشگوئی ہے میںجو تشریح آگے بیان کروں گاوہ جزئی اختلاف کو چھو ڑ کر مقام اورقوم اورزمانہ کے سواایک حد تک حضرت مولوی صاحب کی تحقیق پر مبنی ہوگی.ہاں ایک حصہ جو ان آیا ت کے اصل مقصد کے ساتھ وابستہ ہے آپ کی تحقیق سے باہر رہ گیا تھا اس کی طرف ہم کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بانی سلسلہ احمد یہ نے توجہ دلائی ہے اورو ہ یہ کہ اس پیشگوئی میں مسیح موعود کے دوبار ہ نزول کے متعلق خبریں ہیں اورمسلمانوں کوبتایاہے کہ ویسے ہی حالات آئندہ زمانہ میں مسلمانوںکی ایک جماعت کوبھی پیش آنے والے ہیں (الحکم ۱۰؍ اگست ۱۹۰۵ء صفحہ ۲ کالم ۲).اصحاب کہف کے متعلق اپنی تحقیق ان تمہیدوں کے بعد میں اب اصحاب کہف کے بارہ میں اپنی تحقیق بیان کرتاہوں میں نے جب یہ دیکھا کہ یوسف آرمیتیا کاواقعہ ایک قصہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا.تومیں نے اصحاب کہف کے بارہ میں مزید تحقیق شروع کی.اس تحقیق کے دوران میں میرے خسر ڈاکٹرخلیفہ رشیدالدین صاحب مرحوم ایک کتاب میرے پاس لائے اورکہا کہ اس کتا ب میں جوواقعا ت بیا ن ہوئے ہیں وہ اصحاب کہف کے واقعات سے ملتے ہیں.اس کتاب کانا م روم کے کیٹاکومبز CATACOMBS OF ROME تھا.میں نے وہ کتاب لے کر پڑھی اورمیری بھی یہ رائے ہوئی کہ اس میں بیان کردہ روایات پر اصحاب کہف کی تحقیق کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے.اس کتاب کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ مسیحی ابتدائی زمانہ میں مشرک نہ تھے اوراس کاثبوت اس نے یہ پیش کیا ہے کہ روم کے پاس ایسے غارملے ہیںجن میں ابتدائی زمانہ میں مسیحی لوگ رومی حکومت کے ظلم سے بچنے کےلئے چھپ جایاکرتے تھے.وہاںبہت سے کتبے پائے گئے ہیں جن میں اس وقت کے حالات ہیں.اوران سے معلوم ہوتاہے کہ شروع عیسائیت میں شرک کا نام نہ تھا.اوروہ لوگ مسیح علیہ السلام کو صرف ایک نجات دہندہ نبی سمجھتے تھے.
Page 485
یہ ظلم اس کتاب کے بیان کے مطابق صدیوں تک ہوتارہااورجب ظلم زیادہ ہوتاوہ لو گ ان مقامات میں جاکر چھپ جاتے اورخفیہ طورپر رسد جمع کرکے وہاں رہتے.حتی کہ بعض دفعہ انہیں کئی کئی سال تک وہاں چھپنا پڑاآخرتین سوسال کے بعد جب روم کا ایک بادشاہ عیسائی ہوگیا.توعیسائیوں کی تکلیف دورہوئی ا س کے بعد گاتھ قوم نے روم پر حملہ کیا اوران تہ خانوں کو لوٹ لیا اورتوڑ دیا جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا ذکر مٹ گیا.مگرآثار قدیمہ کے بعض محققین نے روم کے کھنڈرات کی تلاش کرتے ہوئے ان کومعلوم کیااورایک ہزار سال بعد پھر یہ چھپاہواتاریخی مواد دنیا کومعلوم ہوا.میں نے جب یہ کتاب پڑھی تومیں نے یہ سمجھا کہ ہماری تفسیروں میں جو اموربیان کئے گئے ہیں گووہ بہت کچھ رطب و یابس پر مشتمل ہیں مگر ان واقعات کی موجودگی میں انہیں اصل واقعہ سے کلی طو رپر مختلف نہیں کہا جاسکتااورمیں نے نئے سرے سے تفسیروں کے بیا ن کردہ واقعات پر غور کیا چنانچہ میں نے اوپر جو تین روایات بیان کی ہیں.ایک ابن اسحاق کی اوردوکتب احادیث کی ان کو دیکھ کرمیں نے محسوس کیا کہ صداقت کابیج ان روایا ت میں موجود ہے.تفصیلی واقعات جن کا ذکر اصحاب کہف کے متعلق روایات میں آتا ہے اگر اس تفسیر کو پڑھنے والے ایک دفعہ پھر ان روایات کو پڑھ کر دیکھیں گے توانہیں معلوم ہوگا کہ ان روایا ت میں یہ امور بیان ہوئے ہیں (۱) یہ واقعہ مسیحیوں کی ایک قوم سے گذراہے (۲)یہ مظالم رومیوں کے ہاتھ سے ہوئے ہیں (۳)ایک روایت کہتی ہے کہ ایک حواری رومی بادشاہ کے دارالحکومت میں گیا تھا اس وقت وہاں یہ واقعہ گذراہے (۴)دوسری روایت کہتی ہے کہ دقیو س جس کادوسرانام عربوں اورہندوستانیوں میں دقیانو س بھی مشہور ہے.اورجسے لاطینی میں دسیس DECUIS کہتے ہیں.اس کے زمانہ میں اصحاب کہف کاواقعہ ہواہے اوراس سے ڈر کرکچھ مسیحی غار میں چلے گئے تھے (۵)سب روایات متفق ہیں کہ وہ قو م جس نے مظالم کئے تھے بت پر ست تھی.(۶)ایک روایت جسے میں نے لکھا نہیں یہ بھی کہتی ہے کہ اس ملک کے بادشاہ اپنے بتوں کے آگے سجدہ کرنے اوران پر قربانیاں چڑھانے کے لئے مجبورکرتے تھے (۷)حضرت ابن عباسؓ کی روایت بتاتی ہے کہ ان کے زمانہ سے تین سوسال پہلے یہ واقعہ گزراہے (۸)ایک روایت بتاتی ہے کہ تندوسیس کے زمانہ میں اصحاب کہف غار سے باہر نکلے تھے یہ تندوسیس بھی ایک رومی بادشاہ تھا.اوراس کانام لاطینی میں THEODOSIS لکھتے ہیں.کیٹاکومبز کی تاریخ پڑھنے کے بعدیہ روایات بجا ئے ہمارادماغ پریشان کرنے کے ہماری رہنمائی کاموجب
Page 486
ہوجاتی ہیں.اورو ہ اس طرح کہ کیٹاکومبزاورکلیسیا کی تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتاہے کہ فرداًفرداًمسیحیوں پر ظلم تو حضرت مسیح کے واقعہ صلیب سے شروع ہواتھا.مگربحیثیت جماعت نیروکے زمانہ سے روم میں مسیحیوں پر ظلم شروع ہوئے ہیں.اورنیروبادشاہ حواریوں کاہم عصر ہے.اس کا زمانہ حکومت ۵۴ بعد مسیح سے ۶۸ بعد مسیح تک ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ NERO).پرانے عیسائیوں میں یہ عام خیال پایا جاتاہے کہ پطرس کواس کے زمانہ میں پھا نسی دیاگیا.ہمیں کوئی شک نہیں کہ جدید ناقدین تاریخ جو ہرتاریخی واقعہ میں شک پیداکرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس بار ہ میں شک پیداکرنے کی کوشش کی ہے.لیکن پوری تنقید کے بعد بھی وہ اسے رد نہیں کرسکے کہ پطرس روم گیااوروہاں ہی مرا.پرانے مسیحی لٹریچر سے قریباً ۱۷۷ ء بعد صلیب کی ایک تحریر بشپ ڈایو ینسیس کی ملتی ہے جوپیٹر کے روم جانے کی خبر دیتی ہے.چونکہ پطرس واقعہ صلیب کے بعد ستاسٹھ سے ستر اسی سال تک زندہ رہا ہے یہ تحریر کوئی اسی سے سوسال تک پطرس کی وفات کے بعد لکھی گئی ہے اوراتنے قریب کے زمانہ کی شہادت معمولی شہادت نہیں ہوسکتی.خصوصاًجبکہ اس کالکھنے والا گرجے کا بڑاپادری ہے ( انسائیکلو پیڈیا ببلیکا زیرلفظ Simon peter) اصحاب کہف کے واقعہ کا تعلق روم کے ملک سے ہے انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں لکھا ہے کہ یہ امر تاریخ سے ثابت ہے کہ واقعہ صلیب کے دوسوسال کے بعد کے زمانہ میں روم میں پیٹرکی قبر زائروں کو دکھائی جاتی تھی اوریہ کہ ۲۵۸ ء میں اس کی ہڈیا ں کیٹاکومبزمیں منتقل کی گئی تھیں.یہ کہ واقعہ میں و ہ قبر اورہڈیاں پیٹر کی تھیں یانہیں (زیر لفظ Simon peter).انسائیکلو پیڈیا برٹینیکااس بارہ میں لکھتاہے کہ اس کی تحقیق کاسامان ہمارے پاس موجود نہیں.مگر یہ ظاہر ہے کہ جوسامان اَورباتوں کی تحقیقات کے ہیں وہ یہاں بھی ہیں.قریب زمانہ کے لوگ اس واقعہ کو بیا ن کرتے ہیں اوراس کی وفات کے صر ف سواسوسال کے بعد کے زمانہ کاتاریخی ثبوت موجود ہے.کہ روم میں اس کی قبر دکھائی جاتی تھی.غرض یہ امر کہ اسے نیرو نے قتل کیا یانہ کیا.اگر ثابت بھی نہ ہو تب بھی یہ امر ثابت ہے کہ پطرس روم میںگیا اور وہیں مرا اوریہ کہ اس زمانہ میں مسیحیوں پر سختیاں ہوتی تھیں اوران کو ادھر ادھر بھاگ کر جانیں بچانی پڑتی تھیں.(سٹوری آف روم مصنفہ مسٹر ناروڈینگ).پھر ہم کو تاریخ سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ ڈیسس یادقیانوس کے زمانہ میں مسیحیوں پر سختیاں بہت بڑھ گئی تھیں اورقانون بناکر انہیں سزادی جاتی تھی.اورجوبتوں کو سجدہ نہ کرتے تھے ان کو مسیحی سمجھ کر قید یاقتل کیا جاتا تھا.(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ ڈیسیس نیز زیر لفظ تاریخ کلیسیا) ، ڈیسیس کا زمانہ حکومت ۲۴۹ ء ۲۵۱ء تھا.اوراس نے ۲۵۰و ۲۵۱ ء میں مسیحیوں کے خلاف سختی کے قانون پاس کئے تھے.
Page 487
پھر تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتاہے کہ ۳۱۱ ء میں گالیس بادشاہ روم نے مرتے وقت مسیحیوں کے خلاف جوقانون تھا اسے منسوخ کیا(دی ہسٹورین ہسٹری آف دی ورلڈ زیر عنوان The age of diocletian and constantine) قسطنطین شاہ روم ۳۳۷ ء میں عیسائی ہوا.اورتھیو ڈوسیس مشرقی رومی حکومت کے وقت میں مسیحیت بہت پھیل گئی اورپبلک کی طرف سے بھی اسے امن حاصل ہوگیا (انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ کونسٹنٹائن).ان تاریخی شواہد سے ہم پریہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ہیروڈیٹس کے واقعہ سے فلسطین میں اورنیروکے زمانہ سے لےکر ۳۱۱ ء تک روم میں مسیحیوں پرسخت ظلم ہوئے اوریہ کہ مظالم کے زمانہ میں وہ وہا ں سے بھا گ کر ادھر ادھر غاروں میں پناہ لیا کرتے تھے.اصحاب کہف ابتدائی زمانہ کے رومی مسیحی تھے ان واقعات پر نظر ڈال کر ہم کو آسانی سے سمجھ میں آسکتا ہے کہ اصحاب کہف ابتدائی زمانہ کے رومی مسیحی تھے.نیز سینکڑوں سال تک ان پر ظلم ہوتارہا.جس کی ابتداایک مسیح کے حواری کے زمانہ میں ہوئی ڈیسیس کے زمانہ میں ظلم انتہاکوپہنچا اورگالیس کے زمانہ میں ان کو معاف کیاگیا قسطنطین کے زمانہ میں ان کے مظالم قانونی طو ر پرروکے گئے اور تھیوڈسیس کے زمانہ میں انہیں عام ترقی حاصل ہوگئی.اب اگر ان واقعات کی روشنی میں مفسرین کی روایات کودیکھیں تواس مبالغہ کو نظر انداز کرکے جومسیحی اور یہودی راویوں نے کئے ہوں گے وہ روایات اصحاب کہف کاصحیح پتہ ہمیںدےدیتی ہیں او ران میں اختلاف بھی کوئی نہیں.اختلا ف صرف اس وجہ سے معلوم ہوتاتھا کہ لوگ اصحاب کہف کے واقعہ کوکسی ایک جماعت کاواقعہ سمجھتے تھے.لیکن یہ واقعہ درحقیقت ایک جماعت سے یا ایک زمانہ میں نہیں گذرا.بلکہ کئی جماعتوں سے مختلف زمانوں میں گذرا ہے.یہ واقعہ نیروکے وقت میں بھی ہواجبکہ پطرس روم میں موجود تھے.اورابن اسحاق کی روایت اسی وقت کے متعلق ہے اوریہ واقعہ ڈسیس کے وقت میں بھی ہو ا.اورابن المنذر کی روایت اس کے متعلق ہے.معلوم ہوتاہے کہ چونکہ تین سوسال تک مسیحیوں پرظلم ہوتارہااور وہ ظلم کے خاص ایام میں غاروں میں چھپ کر گذاراہ کیا کرتے تھے.ان کی قربانیوں کے کئی واقعات لو گوں میں مشہور ہوگئے تھے.کسی کوپطرس کے زمانہ کاواقعہ معلوم ہواتواس نے سمجھ لیا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بس اتنا ہی ہے.کسی کوڈسیس کے وقت کا کوئی واقعہ معلوم ہوا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہی واقعہ اصحاب کہف کا ہے.غرض مختلف زمانوں کے مظالم اور مسیحیوں کی قربانیوںکی داستانوں کو مظالم کی ساری تاریخ قراردینے سے اختلاف پیداہواہے.جب روایات کو مختلف واقعات سمجھا جائے توپھر عام مبالغہ کوخارج کرکے جوایسی روایات میں ہو جایاکرتا ہے.و ہ سب ہی روایات درست معلوم ہوتی ہیں اورابتدائی مسیحیوں کی پُردرد
Page 488
داستان کاایک مختصر نقشہ ہیں.روم کے کیٹاکومبز کے تاریخی حالات اب میں کہف کے بارے میں مختصراً بعض واقعات بتاتاہوں.جیسا کہ میں بیا ن کرچکا ہوں کہف سے مراد کیٹاکومبز ہیں جوزمین دوز تہ خانوں کانام ہے.رومیو ںاوریہود میں رواج تھا کہ وہ مردوں کو کمروں میں رکھتے تھے.رومی حکومت کے بڑے بڑے شہرو ںمیں شہروں سے باہر ایسی جگہیں بنی ہوئی تھیں اورکیٹاکومبزکہلاتی تھیں.جب مسیحیوں پر ظلم ہوئے توانہوںنے جان بچانے کے لئے ان قبرستانوں میں پناہ لینی شروع کی جس کی دو وجہیں معلوم ہوتی ہیں.ایک تویہ کہ زمین دوز کمروں میں وہ آسانی سے چھپ سکتے تھے.اوربیٹھنے.سونے اورموسم کی شدت سے محفوظ رہنے کابھی سامان ہوتاتھا.دوسر ے اس لئے بھی کہ عام طور پر لوگ قبرستانوں سے ڈر تے ہیں.اوراس طرح لو گوں کی نظروں سے بچنے کاوہاں امکان زیادہ تھا.یہ کیٹاکومبز روم کے پاس.اسکندریہ جومصر کاشہر ہے اس کے پاس.سسلی میں.مالٹامیں.نیپلز کے پاس اس وقت تک دریافت ہوئے ہیں (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Catacombs).مسٹر بنجمن سکاٹ اپنی کتا ب’’د ی کیٹاکومیز اَیٹ روم ‘‘میں لکھتے ہیں.کہ’’میری رائے ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں بھی(جب پولو س روم گیا ہے)عیسائی اپنی حفاظت کے خیال سے لوگوںکے غصہ اور یہودیوں کے ظلموں اوررومی حکومت کے مظالم سے بچنے کےلئے ان تہ خانوں میں پنا ہ لیا کرتے تھے ‘‘.(ص ۶۳)پھر و ہ ذراآگے چل کرلکھتے ہیں.’’وہ یقیناً مجبور تھے کہ ان گڑہوں اورزمین دوز غارو ں میں پنا ہ لیتے ‘‘.اس جگہ مصنف نے ان تہ خانوں کے لئے کیو ( CAVE ) کالفظ استعمال کیا ہے.جو عر بی زبان کے لفظ کہف کا ہی بگڑاہواہے.گویا اس طرح اس انگریز مصنف نے عین وہی لفظ استعمال کردیا ہے جوقرآن کریم نے کیا ہے.یہ کہ ان کوایساکرنے کی ضرورت تھی رومی مؤرخ ٹسیٹس TACITUS کی شہادت سے ثابت ہو جاتا ہے.وہ کہتاہے کہ نیرو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے مسیحیوں کوزندہ جلانے.کتوں سے پھڑوانے.اورصلیب دینے کے مختلف طریق اختیار کررکھے تھے.اورا س غرض سے اس نے اپناشاہی باغ دیاہواتھا.جس قوم پراس قدر اورعام ظلم ہوگا.ظاہر ہے کہ وہ ادھر ادھر بچ کر پناہ لے گی(The Aunals and the histories p.257.258).جب مسیحیو ں نے ان جگہوں پر پنا ہ لینی شروع کی توپنا ہ کے دنوں میں انہوں نے زیاد ہ حفاظت کی خاطران کے اندراورکمرے بنانے شروع کردئے.اسی طرح جو لوگ شہید ہوتے تھے ان کی لاشوں کوبے حرمتی سے بچانے کے لئے بھی و ہ ان تہ خانوں میں لاکردفن کرتے تھے.اور چونکہ یہ سلسلہ تین سوسال تک چلاگیا.اس لئے یہ تہ خانے اس کثرت سے ہوگئے کہ بعض لوگوںکے اندازے کے مطابق وہ پندرہ میل کی لمبائی تک چلے گئے ہیں.
Page 489
چونکہ ظلم یکسا ں نہیں چلتا.درمیان میں بعض باد شا ہ نرمی کرنے لگ جاتے تھے اور مسیحی پھر واپس شہر میں آجاتے تھے.پھر جب سختی کادور آتا توبھاگ کر ان جگہوں میں چھپ جاتے.اورمعلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انہیں وہاں مہینوں یا سالوں رہنا پڑتاتھا.کیونکہ ان کے اندر سکولوں اورگرجوں کی کمرے بھی پائے گئے ہیں.کیٹاکومبز کے چشم دید حالات یہ تہ خانے تین منزل میں بنے ہوئے ہیں.اور ۱۹۲۴ ء میں انگلستان جاتے ہوئے رو م میں میں نے خود ان کواپنی آنکھ سے دیکھا ہے.پہلی منزل کے کمروں کو توانسان بغیر زیادہ تکلیف کے دیکھ سکتا ہے.دوسر ی منز ل میں بہت دم گھٹتاہے.اورتیسری منز ل یعنی سب سے نیچے کے تہ خانہ میں جاناتونمی اورتاریکی کی وجہ سے قریباً ناممکن ہوتاہے.میں نے دیکھا ہے کہ ان تہ خانوں کو مسیحیوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اس طرح بنا لیا تھا جیسے بھول بھلیا ںہوتی ہیں.اورحفاظت کے مندرجہ ذیل طریق ان میں استعمال کئے گئے ہیں.(۱)و ہ لوگ دروازو ں پر کتے رکھتے تھے تااجنبی آدمی کے آتے ہی ان کواس کے بھونکنے سے علم ہوجائے (۲)زمین دوز کمرے جن میں وہ رہتے تھے جہاں سے ان میں زمین کی سطح پر سے داخل ہونے کاراستہ تھا.وہاں مٹی کی سیڑھی نہ ہوتی تھی.بلکہ لکڑ ی کی سیڑھی رکھتے تھے تاکہ اپنا آدمی اترنے کے بعد وہاںسے سیڑھی ہٹادی جاسکے اورتاکہ دشمن آئیں توفوراًکمروں میں نہ پہنچ سکیں.(۳)لیکن اگر وہ کود کر یاسیڑھیاں اپنے ساتھ لاکر اترہی آئیں.تواس کے آگے حفاظت کایہ علاج کیا گیاتھا کہ ہرکمرہ سے چار راستے بنادیئے گئے تھے.ان میں سے ایک راستہ تواگلے کمرہ کی طرف جاتاتھا اورباقی راستے کچھ دور جاکر بندہوجاتے تھے.اس کایہ فائدہ تھاکہ عیسائی توواقف ہونے کی وجہ سے جھٹ اگلے کمرے کی طرف دوڑ جاتے تھے اورتعاقب کرنے والے غلط راستہ کی طرف چلے جاتے اور آگے راستہ بند دیکھ کر پھر دوسرے راستہ کی طرف لوٹتے.اس طرح بار بار غلط راستوں کی طرف جانے کی وجہ سے بھاگنے والے عیسائیوں سے بہت پیچھے رہ جاتے.اول تویہ تعاقب ہی پولیس کو پریشان کردیتاتھا.لیکن اگرآخری حد تک تعاقب کربھی لیتے تو(۴)مسیحی دوسری منزل یعنی نچلے تہ خانوں میں چلے جاتے جوپہلوں سے زیاد ہ تنگ زیادہ تاریک اور زیادہ پیچید ہ ہیں اگربالفرض یہاں تک بھی کامیاب تعاقب کیاجاتا تو(۵)ان سے نیچے تیسرے تہ خانے موجود تھے.جن میں ہم لوگ تودوچار منٹ بھی نہیں ٹھیرسکے.گواس کی ایک وجہ یہ بھی تھی.کہ اب وہ گر کر بہت زیادہ نمناک ہو گئے ہیں.مگر بہرحال وہ بھیانک جگہیں ہیں جہاں غالباً صرف تعاقب کے وقت میں تھوڑی دیر کےلئے مسیحی پنا ہ لیتے تھے.چونکہ سارے راستوں کی لمبائی کئی سومیل تک جاتی ہے.ظاہر ہے کہ ان جگہوں میں عیسائیوں کاپکڑنا آسان کام نہ ہوتاتھا.مگرگورنمنٹ آخر گورنمنٹ ہوتی ہے کئی دفعہ پولیس پکڑ بھی لیتی
Page 490
تھی.اور وہیں ان لوگوں کوقتل کردیتی تھی.میں نے ایسے شہداء کی بہت سی قبریں وہاں دیکھی ہیں.ہم نے بعض کتبے پادری سے پڑ ھواکر معلوم کیا.کہ ان میں وہ درد ناک واقعات بیان کئے گئے ہیںجو شہادت کے وقت ان کو پیش آتے تھے.قریب زمانہ میں جو نئی قبریں اور کتبے دریافت ہوئے ہیں.ا ن میں ان لوگوں کی قبریں بھی ملی ہیں جن کے پاس پطرس ٹھیرے تھے یاجن کابائبل میں ذکر ہے.(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ کیٹاکومبز) ڈسیس کے وقت میں چونکہ قانون بنادیاگیا تھا کہ مسیحی بتوں کو سجدہ کر نے پر مجبورکئے جائیں اوربہت سختی سے مسیحیوں کو ماراجاتا تھا.یہ زمانہ قریباً ساراکاساراعیسائیوں نے کیٹاکومبز میں گذارا.سوائے ان کے جنہوں نے ڈر کر مذہب کو ظاہر اً خیر بادکہہ دیا.اس لئے اس زمانہ میں اصحاب کہف نے ایک نہایت شاندا رمثال قربانی کی پیش کی تھی.کیٹاکومبز کے کتبوں سے جن حالات کا پتہ ملتا ہے ان کتبوں سے جوکیٹاکومبز میں لگے ہوئے ہیں.معلوم ہوتاہے کہ اس وقت مسیحیوں میں شرک نہ تھا.ان کتبوں میں کوئی لفظ شرک کا نہیں.مسیح کو خدا کابیٹا نہیں بلکہ محض ایک گڈریے کی شکل میں دکھایا جاتاہے.ان کی والدہ کے لئے کوئی غیر معمولی عزت کا نشان نہیں ملتا.زیاد ہ تریونس نبی کے واقعہ کو اور حضرت نوح کے طوفان کے آخر میں جو کبوتر اس بات کی خبرلایا تھا کہ پانی ہٹ کرزمین ننگی ہوگئی ہے اس واقعہ کوتصویروں میں دکھا یا جاتا ہے.جس سے معلوم ہوتاہے کہ عہد نامہ قدیم کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑاتھا اور مسیح کوصرف ایک نبی اور روحانی گڈریا خیال کرتے تھے (کیٹاکومبز کے واقعات کے لئے دیکھو انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا.دی کٹاکومبزایٹ روم مصنفہ بنجمین سکاٹ اورڈاکٹر میٹ لینڈ کی کتاب وغیرہ) خلاصہ یہ کہ اصحاب کہف کے واقعہ میں مسیحیوں کے ابتدائی زمانہ کے حالات کو پیش کیا گیا ہے اوربتایا ہے کہ مسیحی قوم کی ابتداء تواس طرح ہوئی تھی کہ وہ بت پرستی کے خلاف جہاد کرتے تھے اورشرک سے بچنے کے لئے انہوں نے صدیوں تک بڑی بڑی قربانیا ں کیں.لیکن انتہاء ا س طرح ہوئی ہے کہ اصلی دین کاکوئی نشان بھی اب مسیحیوں میں نہیں پایاجاتا.
Page 491
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ١ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا ہم ان کی اہم خبر بالکل صحیح طور پر تیرے پاس بیان کرتے ہیں.وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر (حقیقی)ایما ن بِرَبِّهِمْ وَ زِدْنٰهُمْ هُدًىۗۖ۰۰۱۴ لائے تھے اورانہیں ہم نے ہدایت میں (اوربھی )بڑھایاتھا.حلّ لُغَات.نَقُصُّ.نَقُصُّ قَصََّّ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے.اس کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر۴.قَصَّ یَقُصُّ قَصًّا وقَصَصًا اَثَرَہُ: تَتَبَّعَہُ شَیْئًا بَعْدَ شَیْءٍ.اس کا نشان تلاش کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا.وَمِنْہُ فَارْتَدَّا عَلَی اٰثَارِھِمَا قَصَصًا.اَیْ رَجَعَا فِی الطَّرِیْقِ الَّتِیْ سَلَکَا ھَا یَقُصَّانِ الْاثرَ.اور انہی معنوں میں قرآن کریم کی آیت فَارْتَدَّاعَلَی اٰثَارِھِمَا قَصَصًا میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.قَصَّ عَلَیْہِ الْخَبَرَ وَالرُّؤْیَا: حَدَّثَ بِھِمَا عَلٰی وَجْھِھِمَا بات کو بے کم و کاست بیان کیا.ٹھیک طور پر بیان کیا.وَمِنْہُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ.اَیْ نُبَیِّنُ لَکَ اَحْسَنَ الْبَیَانِ.اور انہی معنوں میں سورہ یوسف کی آیت نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ میں یہ لفظ آیا ہے.یعنی ہم تیرے سامنے ٹھیک ٹھیک بات بیان کرتے ہیں.(اقرب) نَبَاٌ نَبَاٌکے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر۳۸.نَبَّأَہُ الْخَبْرَ وَبِالْخَبْرِ: خَبَّرَہٗ.خبر دی.آگاہ کیا.ویُقَالُ نَبَّأْتُ زَیْدًا عَمْرًا مُنْطلِقًا.بتایا.علم دیا.النَّبَأُ: اَلْخَبَرُ.خبر.وَقَالَ فِی الْکُلِّیَاتِ النَّبَأُ وَالْاَنْبَاءُ لَمْ یَرِدَا فِی الْقُرْاٰنِ اِلَّا لِمَا لہٗ وَقْعٌ وشأْنٌ عَظِیْمٌ.اور کلیات ابوالبقاء میں ہے کہنبأ کا لفظ یا انباء کا لفظ جہاں بھی قرآن کریم میں آیا ہے کسی ذی عظمت اور ذی شان چیز یا بات کی خبر کے متعلق ہی آیا ہے.(اقرب) اَلْحَقُّ کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر۱۵.اَلْحَقُّ.حقَّ کا مصدر ہے.اور حَقَّہٗ حَقًّا کے معنے ہیں غَلَبَہٗ عَلَی الْحَقّ.حق کی وجہ سے اس پر غالب آیا.وَالْاَمْرَ: اَثْبَتَہٗ وَاَوْجَبَہٗ.کسی امر کو ثابت کیا اور واجب کیا.کَانَ عَلٰی یَقِیْنٍ مِنْہٗ.کسی معاملہ پر یقین سے قائم تھا.اَلْخَبَرَ: وَقَفَ عَلٰی حَقِیْقَتِہِ اور حَقَّ الْخَبَر کے معنے ہوں گے اس کی حقیقت سے آگاہ ہوا اور الحقُّ کے معنے
Page 492
ہیں ضِدُّ الْبَاطِلِ سچ.اَلْاَمْرُ الْمَقْضِیُّ فیصلہ شدہ بات.اَلْعَدْلُ.عدل.اَلْمِلْکُ.ملکیت.اَلْمَوْجُودُ الثَّابِتُ.موجود و قائم.اَلْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ.یقین.المَوْتُ.موت الحَزْمُ دانائی.(اقرب) تفسیر.نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِِّّ.یعنی ہم تیرے سامنے ان کے واقعات جس طرح ہوئے ہیں اسی طرح بیان کرتے ہیں.ا س سے معلو م ہوتاہے کہ جوپرانے قصے تھے وہ صحیح نہ تھے.اوریہ بھی پتہ لگاکہ اس وقت کچھ قصے ان کے متعلق ضرور مشہور تھے.اس امر کاثبو ت کہ ان کے بارہ میں کچھ قصے ضرور مشہو رتھے پہلی آیات سے بھی ملتاہے.کیونکہ قرآنی واقعہ تواس آیت سے شروع ہوتاہے.اس سے پہلے جوبیان کیاگیا تھا معلوم ہوتاہے وہ اس وقت کی مشہور روایتوں کاصحیح خلاصہ تھا.فتًی کے معنے اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ.وہ نوجوانوں یا شریف اورسخی لوگوں کی ایک جماعت تھی جواپنے رب پر ایمان لائی فَتًی کے معنے سخی.شریف.لوگوں کے لئے مال خرچ کرنے والا.یانوجوان کے ہیں (اقرب).کیونکہ دینی کاموں میں نوجوان ہی زیادہ حصہ لیتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے والے سوائے چند کے باقی سب آپ سے عمر میں کم تھے.وَ زِدْنٰهُمْ هُدًى.اورہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کردیاتھا.یعنی ان کی قربانیوںکی وجہ سے ہم نے ان کے ایمانوں کو بہت بڑھادیاتھا.اِنَّهُمْ فِتْيَةٌمیں خاص پارٹی کا ذکر فِتْیَۃٌ سے یہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ مختلف پناہ لینے والی پارٹیوں میں سے کسی خاص پارٹی کا جوسب سے زیاد ہ قربانی کرنے والی تھی.اس جگہ ذکر کیا گیا ہو.اوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں کسی خاص جماعت کا ذکر نہ ہو.بلکہ یہ مراد ہو کہ شریف مسیحی جواپنے دین میں پکے ہوتے تھے.ایسا کیاکرتے تھے.اورا س طرح اس آیت میں تین سوسال کے عرصہ میں جس قدر لوگوں نے قربانیاں کی تھیں.سب ہی کا ذکر ہو.میں ذاتی طورپر ان آخری معنوں کوترجیح دیتاہوں.
Page 493
وَّ رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ اورجب و ہ(اپنے وطن سے نکلنے کے لئے )اٹھے توہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کردیا تب انہوں نے (ایک وَ الْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَاۡ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا دوسرے سے )کہا (کہ)ہمارارب (و ہ ہے جو )آسمانوں اورزمین کا(بھی)رب ہے ہم ا س کے سواکسی اور معبودکو شَطَطًا۰۰۱۵ ہرگز (کبھی )نہیں پکاریں گے ورنہ ہم ایک حق سے دور بات کہنے والے ہوں گے.حلّ لُغَا ت.رَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ رَبَطَ الشَّیْءَ (یَرْبِطُ وَیَرْبُطُ )کے معنے ہیں.اَوْثَقَہٗ وَ شَدَّہٗ.کسی چیز کو مضبوط طور پر باندھ دیا.رَبَطَ جَاْشُہٗ(رَبَاطَۃً)کے معنے ہیں: اِشْتدَّ قَلْبُہٗ اس کادل مضبوط ہوگیا.رَبَطَ اللہُ عَلٰی قَلْبِہٖ :صَبَّرَہٗ.اللہ نے مصائب کے برداشت کی اسے طاقت دی اورقدم نہ لڑکھڑانے دیا.(اقرب) شَطَطًا:شَطَّ(شَطَطًا)کے معنے ہیں :جَارَ.ظلم کیا.اَفْرَطَ.زیادتی کی.شَطَطَ فِی سِلْعَتِہٖ شَطَطًا.جَاوَزَالْقَدْرَ الْمَحْدُوْدَ اپنے سامان میں مقرراندازہ سے بڑھ گیا.تَبَاعَدَ عَنِ الْحَقِِّّ.حق سے دور ہوگیا.شطَّ فِی السَّوْمِ:غَالَی فِی الثَّمَن.قیمت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا.نیز شَطَطٌ کے معنے ہیں مُجَاوَزَۃُ القَدْرِ وَالْحَدِّ.حداوراندازہ سے آگے گذرجانا (اقرب) تفسیر.باوجود اس کے کہ بادشاہ اوررعایا سب ہی ان کے مخالف تھے.اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کوطاقت دی اورصبر بخشا.اورو ہ سب کے مقابل پر کھڑے ہوکر اپنے عقیدہ کااظہار کرتے رہے.هٰؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً١ؕ لَوْ لَا يَاْتُوْنَ ان لوگوں نے یعنی ہماری قوم نے اس (معبودبر حق )کوچھوڑ کر (اپنے لئے )اور(اور)معبود بنالئے ہیں وہ ان کے عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَيِّنٍ١ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى ثبوت میں کیوںکوئی روشن دلیل نہیں لاتے.پھر (و ہ کیوں نہیں سمجھتے کہ )جوشخص اللہ (تعالیٰ )پر جھوٹ باندھے
Page 494
اللّٰهِ كَذِبًاؕ۰۰۱۶ اس سے بڑھ کر ظالم کون (ہوسکتا )ہے.حلّ لُغَات.سُلْطٰن سُلْطٰنٌ کے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر ۱۱.السُّلْطَانُ: اَلْحُجّۃُ.سلطان کے معنے ہیں دلیل.التَّسَلُّطُ.قبضہ وَقُدْرَۃُ المَلِکِ.بادشاہ کی طاقت (اقرب) بَیِّن اَلْبَیِّنُ:اَلْوَاضِحُ الْجَلِیُّ.بالکل واضح (اقرب) تفسیر.اس سے معلوم ہوتاہے کہ قرآن کریم کے نزدیک جس قوم میں سے اصحاب کہف نکلے تھے و ہ بت پرست تھی اور کئی معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے.یہی حال رومیوں کاتھا.ان میں بھی کئی بت پوجے جاتے تھے.اس سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ یہ موحدوں کی جماعت کوئی پراگندہ نوجوان نہ تھے.بلکہ ایک مذہب سے تعلق رکھتے تھے اورآپس میں ملتے رہتے تھے.کیونکہ اس آیت کامضمون بتاتاہے کہ و ہ لوگ یہ باتیں باہم علیحد گی میں کیاکرتے تھے.وَ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاْوٗۤا اِلَى اور(اب اس وقت )جب (کہ)تم نے ا ن سے اور(نیز )اللہ (تعالیٰ)کے سواجس چیز کی (بھی )وہ پرستش کرتے الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ ہیں اس سے کنارہ کشی کرلی ہے تو(اب )تم اس وسیع پہاڑی پناہ گاہ میں پناہ لو (ایساکروگے تو)تمہارارب اپنی مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا۰۰۱۷ رحمت (کی کوئی راہ)تمہارے لئے کھو ل دے گا اور تمہارے لئے تمہارے (اس )معاملہ میں کوئی سہولت کاسامان مہیا کردے گا.حلّ لغات.یَنْشُر یَنْشُرُنَشَرَسے مضارع واحد مذکر غائب کاصیغہ ہے.اورنَشَرَالثَّوبَ
Page 495
وَالْکِتَابَ کے معنے ہیں بَسَطَہٗ خِلَافَ طَوَاہُ کسی کتاب کو کھولااو رکپڑے کوپھیلا یا.نَشَرَتْ اَوْرَاقُ الشَّجَرِ: اِمْتَدَّتْ وَانْبَسَطَتْ.درخت کے پتے پھیل گئے.نَشَرَ الْخَبَرَ نَشْرًا.اَذَاعَہٗ.کسی خبر کوپھیلا یا (اقرب) مِرْفَقًا.رَفَقَ بہٖ وَعَلَیْہِ وَلَہٗ( یَرْفُقُ مِرْفَقًا)کے معنے ہیں لَطُفَ وَلَمْ یُعَنِّفْ.اس پر نرمی کی اورسختی سے کا م نہ لیا (اقرب)پس مِرْفَقٌ کے معنے ہوئے نرمی.تفسیر.الکہف سے خاص جگہ کی طرف اشارہ یہاں پر جواَلْکَھْفِ کالفظ ا ستعمال کیا گیاہے.یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں کوئی خاص جگہ تھی.ورنہ وہ اِلٰی کَھْفٍ کہتے کہ کسی غار کی طرف چلے جانا.مگروہ اِلٰی کَھْفٍ نہیں کہتے.بلکہ اِلَی الْکَھْفِ کہتے ہیں.جس سے معلو م ہوتاہے کہ ان کے علاقہ میں کوئی خاص کہف(غار)تھی.جومشہور تھی.اوراس کی طرف اشار ہ کرنے سے ہرایک شخص اس مقام کوپہچان جاتاتھا.دوسرے اس سے یہ معلوم ہوتاہے کہ اس کہف میں جانے سے پہلے دیرسے ا ن پر ظلم ہورہاتھا اورانہوں نے آپس میں یہ سکیم کررکھی تھی کہ جب ظلم حد سے بڑ ھ جائے اورباہر رہنا مشکل ہوتواس کہف میں چلے جائیں گے کیونکہ اِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ بتاتاہے کہ ان کابائیکاٹ ہوچکاتھا اوروہ اپنی قوم سے الگ اپنے جتھے میں رہتے تھے.اس کہف (غار)کی شہر ت پہلے سے اس وجہ سے تھی کہ رومی غلامو ں پر جب ان کے آقا بہت ظلم کیا کرتے تھے تووہ بھاگ کر وہاں چلے جایا کرتے تھے.وہ بھی ان کی مثال پر عمل کرناچاہتے تھے.پس انہوں نے باہم مشور ہ کرکے فیصلہ کرلیا کہ اگرظلم بڑھ جائے اورباہررہنا دین کے لئے مضرہو تو اس غار میں چلے جائیںجہاں غلام بھاگ کرجایا کرتے تھے.اگرچہ وہ غا رانہی لوگوںنے بہت کچھ بڑھائی لیکن و ہ پہلے بھی بہت وسیع تھی.وَ تَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَّزٰوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اور(اے مخاطب )توسورج کو دیکھتاہے کہ جب و ہ چڑھتاہے توان کی وسیع جائے پنا ہ سے دائیں طر ف کوہٹ کر الْيَمِيْنِ وَ اِذَا غَرَبَتْ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِيْ گذرتا ہے اورجب و ہ ڈوبتاہے توان سے بائیں طرف کو ہٹ کرگذرتا ہے اوروہ اس (کہف )کے اندرایک فراخ
Page 496
فَجْوَةٍ مِّنْهُ١ؕ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ١ؕ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ جگہ میں (رہتے )ہیں.یہ بات اللہ(تعالیٰ کی نصرت )کے نشانوں میں سے(ایک نشان)ہے جسے الْمُهْتَدِ١ۚ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ اللہ (تعالیٰ ہدایت کا)راستہ دکھائے وہی ہدایت پر ہوتا ہے اورجسے وہ گمراہ کر ے اس کاتو(کبھی )کوئی دوست وَلِيًّا مُّرْشِدًاؒ۰۰۱۸ (اور)راہ نمانہیں پائے گا.حلّ لُغَات.تَزٰوَرُ.تَزٰوَرُاصل میں تَتَزَاوَرُہے اور تَزَاوَرَ سے مضارع مؤنث غائب کاصیغہ ہے.اور تَزَاوَرَعَنْہُ کے معنے ہیں عَدَلَ وَ اِنْحَرَفَ منحرف ہوگیا.اورعلیحد ہ ہوگیا(اقرب)باب تفاعل سے پہلے جومضارع کی تاء آتی ہے بوجہ دو’’ت ‘‘جمع ہوجانے کے.ان میں سے پہلی ’’ت‘‘ کو حذف کردینے کی عربی میں اجازت ہے.تَقْرِضُھُمْ.تَقْرِضُھُمْ قَرَضَ سے مضارع مؤنث غائب کاصیغہ ہے.قَرَضَ الشَّیْءَ (یَقْرِضُ قَرْضًا) کے معنے ہیں قَطَعَہُ کسی چیز کوکاٹا.قَرَضَ الْوَادِی :جَازَہٗ.وادی کو طے کیا.قَرَضَ الْمَکَانَ: عَدَلَ عَنْہُ وَتَنَکَّبَہٗ کسی چیزسے علیحدہ اور ایک طرف ہوگیا (اقرب) اَلْفَجْوَۃُ اَلْفُرْجَۃُ بَیْنَ الشَّیْئَیْن دوچیزوں کے درمیا ن کشادہ جگہ.مااتَّسَعَ مِنَ الْاَرْضِ.وسیع زمین.سَاحَۃُ الدَّارِ گھر کاصحن (اقر ب) مُرشِدًا مُرشِدًااَرْشَدَ سے اسم فاعل ہے اورارشد کے معنے ہیں ھداہُ اسے راستہ دکھایا.۲.بتایا اورواضح کیا.۳.اوراس کے آگے چل کر منزل مقصود تک لے گیا.۴.ایمان کی طرف راہنمائی کی (اقرب) تفسیر.اصحاب الکہف کے غار کا جائے وقوع اس آیت میں غار کا مقام بتایا گیاہے.آیت میں جو علامات بتائی گئی ہیںان سے ظاہر ہے کہ یہ قوم اونچے شمالی علاقوں میں بسنے والی تھی کیونکہ جب شمال کی طرف جائیں اورمشرق کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوں توسورج دائیں طرف رہتاہے اورجب جنوب میں آئیں اورمشرق کی طرف منہ کریں توبائیں طرف رہتاہے.یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ اس غا ر کامنہ شمال مغرب کی طرف تھا.جوعمارت
Page 497
شمالی ر خ ہوگی اس سے سورج دائیں سے بائیں کوہی گزرے گا.فَـجْوَةٌ سے پتہ لگتاہے کہ اند روسیع علاقہ تھا.چنانچہ ان غاروں کے دیکھنے سے تصدیق ہوجاتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی وسیع جگہ ہے.بعض نے اس کی گلیو ںاوراوپر نیچے کے تہ خانوں کا مجموعی اندازہ ۸۷۰میل تک کالگایا ہے (یعنی اگر سب گلیوں اورکمروں کو ایک دوسرے کے آگے رکھتے چلے جائیں)اوریہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہاں روشنی بہت کم پڑتی تھی.ورنہ لوگ پکڑے جاتے.انہوں نے غار کوایسی طرز پر بنایاکہ ہوابھی آئے اوران کاپتہ بھی نہ لگے.چنانچہ سینٹ جیرون چوتھی صدی میں لکھتاہے کہ و ہ کمرے اس قد ر تاریک ہیںکہ حیرانی ہوتی ہے.کہیں سے عمارت پھٹی ہوئی ہی ہوتوسورج کی کوئی شعاع پڑ سکتی ہے ورنہ نہیں (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Catacombs of Rome).اس کی جائے وقوع بتانے سے یہ مقصد تھاکہ شمال میں کوئی مسلمانوں کادشمن ہے مسلما ن اس سے ہوشیار رہیں مگرمسلمانوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس طر ف توجہ نہیں کی.اورپھر مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ میں یہ بتایاہے کہ ہم نے اشار ہ توکردیا ہے مگرسمجھ وہی سکتاہے جوہدایت پر ہو.یعنی ان قوموں سے جو دوستانہ سلوک کرے گا وہ ہلاک ہوگا اورجو آپس میں اتفاق کریں گے کامیاب ہوں گے مگرمسلمانوں نے آپس میں لڑائیاں کیں لیکن روم کے بادشاہوں سے صلح رکھی.سوائے ابتدائی زمانہ کے کہ جب رومی بادشاہ نے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کی جنگ کی خبر معلوم کرکے اسلامی مملکت پر حملہ کرناچاہاتوحضرت معاویہؓ نے اسے لکھا کہ ہوشیا ر رہنا ہمارے آپس کے اختلاف سے دھوکا نہ کھانا اگرتم نے حملہ کیا توحضرت علیؓ کی طرف سے جوپہلا جرنیل تمہارے مقابلہ کے لئے نکلے گاوہ میں ہوں گا.اس کے برخلاف جب مسلمان اسلام سے دورجاپڑے توبغداد کے بادشاہو ں نے سپین کو نقصان پہنچانے کے لئے مشرقی رومی حکومت سے جوبازنطینی حکومت کہلاتی تھی صلح کی.اورسپین کے مسلمان بادشاہوں نے بغدادی حکومت کے خلاف مددلینے کے لئے پاپائے روم کوتحفے بھیجے اوراس سے صلح کی.اِنَّالِلہِ وَاِنَّااِلَیْہِ رَاجِعُونَ.اس نکتہ کی طرف مجھے قرآنی حروف مقطعات آلمٓرٰ نے توجہ دلائی اورمسلمانوں کی یہ دردناک اورعبرتناک غلطی مجھے معلوم ہوئی.
Page 498
وَ تَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّ هُمْ رُقُوْدٌ١ۖۗ وَّ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ اور(اے مخاطب)توانہیں بیدار سمجھتاہے.حالانکہ وہ سوتے ہیں.اورہم انہیں الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ١ۖۗ وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ دائیں طرف (بھی)پھرائیں گےاوربائیں طرف (بھی)اوران کا کتّا (بھی ان کے ساتھ ساتھ)صحن میں ہاتھ بِالْوَصِيْدِ١ؕ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَّ پھیلائے(موجود )رہے گا.اگر توان کے حالات سے آگاہ ہوجائے توتو اُن سے بھاگنے کے لئے پیٹھ پھیر لے لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۰۰۱۹ اوران کی وجہ سے رعب سے بھر جائے.حلّ لُغَات.تَحْسَبُھُمْ.تَحْسَبُھُمْ حَسِبَ (یَحْسَبُ)سے مضارع کاصیغہ ہے.اورحَسِبَہُ کے معنے ہیں ظَنَّہُ اس کے بارے میں گما ن کیا (اقرب) اَیْقَاظًا.یہ یَقِظٌ وَیَقُظٌ وَیَقْظَانٌ کی جمع ہے اوریَقِظٌ وَ یَقُظٌ ویَقْظَانٌ صفت مشبہ کے صیغے ہیں اور یَقِظَ الرَّجُلُ(یَقَظًا)کے معنے ہیں :ضِدُّ نَامَ وَتَنَبَّہَ لِلْاُمُوْرِ وَحَذِروَفَطِنَ.و ہ بیدار رہا.معاملات میں محتاط ہوا.چوکس ہوا،.سمجھدار ہوا.(اقرب) رُقُوْدٌ رُقُودٌ رَاقِدٌ کی جمع ہے.اوریہ رَقَدَ سے اسم فاعل ہے اوررَقَدَ الرَّجُلُ ( یَرْقُدُ.رَقْدًا وَ رُقُوْدًا وَ رُقَادًا)کے معنے ہیں :نَامَ.سوگیا.رَقَدَالْـحَرُّ:سَکَنَ.گرمی ہٹ گئی.رَقَدَ عَنِ الْاَمْرِ:غَفَلَ.کسی کام سے غافل ہوا.رَقَدَالثَّوبُ :اَخْلقَ.کپڑابوسید ہ ہوگیا.اور اَلرَّاقِدُ کے معنے ہیں.اَلنَّائِمُ.سویاہوا.اس کے علاوہ اس کی جمع رُقَّدٌ بھی آتی ہے (اقرب) نُقَلِّبُھُمْ نُقَلِّبُھُمْ قلَّبَ(باب تفعیل)سے مضارع جمع متکلم کاصیغہ ہے اورقَلَّبَہٗ کے معنے ہیں حَوَّلَہٗ عَنْ وَجْھِہِ.اس کو اصل مقصد سے پھیر دیا.قَلَّبَ الشَّیءَ: حَوَّلَہٗ وَجَعَلَ اَعْلَاہُ اَسْفَلَہُ.کسی چیز کو اس طرح تبدیل کیا کہ اس کے نیچے کی سطح اوپر آگئی.قَلَّبَ الشَّیْءَ لِلْاِبْتِیَاعِ:تَصَفَّحَہُ فَرَأَی دَاخِلَہٗ وَبَاطِنَہٗ.کسی چیز کو
Page 499
خرید نے کے لئے اس کے متعلق پوری واقفیت اورپوراعلم حاصل کرلیا.قَلَّبَ الْاَمْرَ ظَھْرًا لِبَطَنٍ.اِخْتَبَرَہٗ.معاملہ کاامتحا ن کیا.قَلَّبَ الْقَوْمَ :صَرَفَہُمْ.لوگوں کورخصت کیا (اقرب) وَصِیْدٌ.وَصِیْدٌ:اَلْفِنَاءُ گھر کاصحن.اَلْعَتَبَۃُ.دروازہ کی دہلیز.بَیْتٌ کَالْحَظِیْرَۃِ یُتَّخَذُ مِنَ الْـحِجَارۃِ لِلْمَالِ اَیِ الْغَنَمِ وَغَیْرِھَا فِی الْجِبَالِ.باڑے کی طرح کاچھوٹاسامکان جو پتھروں سے پہا ڑی جگہوں میں جانوروں کے لئے بناتے ہیں.اَلْجَبَلُ.پہاڑ.اَلنَّبَاتُ الْمُتَقَارِبُ الْاُصُولِ.چھوٹے تنوں والے پودے.اَلضَّیْقُ وَ الْمُطْبَقُ.تنگ (اقرب) تفسیر.میرے نزدیک اس آیت میں اصحاب کہف کے ابتدائی ایام کا ذکر نہیں بلکہ ان کی اس وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے جوقرآن کریم کے وقت میں تھی اوریہ بتایاگیاہے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ شمالی اقوام جاگ رہی ہیں.و ہ جاگ نہیں رہیں اس وقت وہ سورہی ہیں.آئندہ زمانہ میں جاگیں گی.گویا ان کی موجودہ حالت آئندہ کی حالت کے مقابل پر ایسی ہے کہ ان کوسوتے ہوئے سمجھنا چاہیے.اس سے اس طرف اشارہ کیاہے کہ ان دنوں میں تم ان کے زور کوتوڑدوتوآئندہ ان کے شرسے محفوظ رہو گے.مگر افسوس حضرت عثمان ؓ کے بعد سے اس قوم کی طرف مسلمانوں کی توجہ کم ہوگئی.اگر اس وقت مسلمان حملہ کرکے بازنطینی حکومت کو تباہ کردیتے اوراس کاان کو حق تھا.کیونکہ رومیوں نے حملہ کرنے میں پہل کی تھی.تویقیناً آج دنیا کانقشہ مختلف ہوتا.وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ میں بتایا ہے کہ ان کو آئندہ زمانہ میں ہم دنیا پر پھیلانے والے ہیں وہ وقت ان کی بیداری کاہوگا.پس اس وقت کے آنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لئے تدابیر کرلینی چاہئیں.اصحاب کہف کے کتے کی تشریح وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ سے رومی بازنطینی حکومت کی طر ف اشارہ ہے جو بحیرہ مارمورہ کے دونوں جانب یورپ کی حفاظت کررہی تھی.اگربحیرہ مار مورہ کودیکھا جائے توبالکل یوںمعلوم ہوتاہے کہ کوئی کتادائیں بائیں لاتیں پھیلائے پہر ہ دے رہاہے.ترکوں نے اس علاقہ کو فتح کیا مگر اس وقت تک مقابلہ کااصل موقعہ نکل چکا تھا اورشمالی قومیں طاقت پکڑ چکی تھیں.جن کاترک مقابلہ نہ کرسکتے تھے.اگر بغداد اورسپین کی حکومتیں مل کر اپنے زمانہ میں شمالی ملکوں میں پھیل جاتیں تووہ ایک زریں موقعہ تھا.یقیناً اس وقت اسلا م ان ممالک میں پھیل جاتا اورآج کے تاریک دن دیکھنے میں نہ آتے.کہاجاسکتاہے کہ الٰہی تقدیر کو کس طرح روکا جاسکتاتھا لیکن یہ اعتراض الہامی کلام کی حقیقت کی نافہمی سے پیدا ہوگا.الٰہی قانو ن یہ ہے کہ انذاری پیشگوئیاں ٹل بھی جاتی ہیں.کم سے کم اسلام کو جو ضعف آج پہنچ رہاہے.
Page 500
ان حالا ت میں وہ ایساشدید نہ ہوتا اوریو رپ میں اسلام کے ہمدرداورمددگار موجود ہوتے جومسیحی حملہ کی شدت کو بہت کم کردیتے.یہ جوفرمایا کہ اگر تجھے ان کاعلم ہو تو تُوان سے مرعوب ہوجائے.اس کاتعلق ا س وقت سے ہے جبکہ ان کو شمال اورجنوب میں پھیلادیاجائے گا.چنانچہ دیکھ لو.اس وقت ان شمالی قوموں کاکس قدر رعب ہے.دنیا کی دوسری حکومتیں اگر کوئی ہیں بھی توان کے رحم پر ہیں.اوران کارعب سب دنیا پر چھایا ہواہے.وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ سے اس طر ف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان قوموں میں کتے رکھنے کابہت رواج ہوگا.چنانچہ دیکھ لویوروپین قومیں عام طور پر کتے رکھتی ہیں جوان کے گھروں کے پہرے دیتے ہیں اورپہلاخوف ان کی کوٹھیو ں پرجانے والے کے لئے ان کے کتوں سے ہی پیدا ہوتاہے.لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم مخاطب نہیں ہوسکتے.کیونکہ یہ نُقَلِّبُهُمْ کے بعد کی حالت کے اثر کابیان ہے.پس اس میں ہرسننے والا ہی مخاطب ہو سکتا ہے.یعنی ہرایک پر اُن کا رعب طاری ہوجائے گا.چنانچہ کچھ عرصہ پیشتر توساری دنیا میں ہی اس قوم کارعب ماناجاتاتھا.اب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تباہی کے سامان پیداکرکے دنیا سے اس کے رعب کوکم کردیا ہے.ورنہ اس قوم کاپہلے اس قدر رعب تھا کہ لوگ ریل گاڑی کے اول ودوم درجہ میں بیٹھنے تک سے بھی خو ف کھاتے تھے.اوریوروپین لوگوں کی شکل تک دیکھنے سے مرعوب ہوجاتے تھے.وَ كَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ١ؕ اوراسی طرح ہم نے انہیں (بےکسی کی حالت سے )اٹھایا اس پر وہ آپس میں (حیرت سے )ایک دوسرے سے سوال قَالَ قَآىِٕلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ١ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ کرنے لگے( اور)ان میں سے ایک کہنے لگا (کہ )تم (یہاں )کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو (جواس کے مخاطب تھے ) بَعْضَ يَوْمٍ١ؕقَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ١ؕ انہوں نے کہا (کہ)ہم ایک دن یادن کاکچھ حصہ ٹھہرے ہیں.(تب)انہوںنے( یعنی دوسروں نے)کہا (کہ )
Page 501
فَابْعَثُوْۤا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ جو(عرصہ)تم (یہاں)ٹھہرے رہے ہو اسے تمہارارب(ہی)بہتر جانتا ہے پس (اس بحث کو چھوڑواور )یہ اپنے فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَاۤ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ روپے دےکر اپنے میںسے کسی ایک کواس شہرکی طرف بھیجو اوروہ (جاکر )دیکھے کہ اس (شہر)میں سے کس کاغلہ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ لْيَتَؔلَطَّفْ وَ لَا يُشْعِرَنَّ سب سے اچھا ہے پھر (جس کاغلہ سب سےاچھا ہو )اس سے کچھ کھانے کاسامان لے آئے اوروہ ہوشیاری سے بِكُمْ اَحَدًا۰۰۲۰ (لوگوںکی )راز کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرے.اور تمہارے متعلق کسی کو ہرگز (کوئی)علم نہ ہونے دے.حلّ لُغَات.بِوَرِقِکُمْ.اَلْوَرَقُ :اَلدَّرَاھِمُ اَلْمَضْرُوْبَۃُ.سرکاری مہر والے سکے.(اقرب) اَزْکٰی زَکَاالشَّیءُ( یَزْکُوْ)نَمَا.کوئی چیز بڑھ گئی.زَکَا الرَّجُلُ:صَلُحَ وَتَنَعَّمَ وَکَانَ فِیْ خِصْبٍ.کسی شخص کی حالت درست ہوگئی.اورو ہ آسودہ حال ہوگیا اورخوب عیش سے رہنے لگا(اقرب)الزَّکاةُ کے معنے: الطَّھَارَۃُ.پاکیزگی.والنَّمَـاءُ وَالْبَرَکَۃُ.ہر چیز کابڑھنا اوراس میں برکت کاہونا.(تاج) اَلطَّعَامُ.الطَّعَامُ: اِسْمٌ لِمَا یُؤْکَلُ.خوراک.کھانا.وَقَدْ غَلَبَ الطَّعَامُ عَلَی الْبُرِّ.اورزیادہ گند م پر طعام کالفظ بولاجا تا ہے.وَرُبَّمَا اُطْلِقَ عَلَی الْحُبُوبِ کُلِّھَا.اوربسا اوقات تمام قسم کے دانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے.(اقرب) الرّزق.الرِّزْقُ :مایُنْتَفَعُ بہٖ.ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھا یاجائے.مَایُخْرَ جُ لِلْجُنْدِیِّ رَأْسَ کُلِّ شَھَرٍ.ہرما ہ کے اخیر پر تنخواہ جو سپاہی کو دی جائے (اقرب) وَلْیَتَلَطَّفُ:وَلْیَتَلَطَّفُ تَلَطَّفَ.(باب تفعّل)سے امر کاصیغہ ہے اورتَلَطَّفَ الْاَمْرَوَفِی الْاَمْرِکے معنے ہیں تَرَفَّقَ فِیْہِ.اس نے کسی معاملہ میں نرمی کی.تَخَشَّعَ.عاجز ی کی.تَلَطَّفَ بِفُلَانٍ:اِحْتَالَ لَہٗ حتّٰی
Page 502
اِطَّلَعَ عَلٰی اَسْرَارِہِ اس نے حیلوں کے ذریعہ سے اس کے بھیدوں پر اطلا ع پائی (اقرب) وَلَایُشْعِرَنَّ بِکُمْ.یُشْعِرَنَّ شَعَرَ کے باب افعال کاصیغہ مضارع واحد مذکر غائب ہے.شَعَرَ کے لئے دیکھو سورئہ یوسف آیت نمبر ۱۰۸.شَعَرَبِہِ.عَلِمَ بِہِ.معلوم کیا.لِکَذَا: فَطِنَ لَہٗ.اس کو سمجھا.عَقَلَہٗ.اس کو پہچانا.اَحَسَّ بِہٖ.محسوس کیا.(اقرب) تفسیر.اس جگہ بھی ان اصحاب کہف کا ذکر نہیں جوابتدائی ایام میں غاروں میں چھپتے تھے.بلکہ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ کے وقت کاحال بتایا ہے اوربَعَثْنٰھُمْ سے مراد آئندہ زمانہ میں شمالی اقوام کی ترقی کاجومسیحی ہو چکی ہوں گی ذکر کیا گیاہے.ماضی کے صیغہ سے آئندہ کی خبر دینا قرآن کریم کاعام محاورہ ہے اورجیساکہ متعدد بار پہلے ثابت کیاجاچکا ہے.ماضی کے صیغہ سے آئند ہ کی خبر دینے سے اس کے یقیناً واقع ہوجانے کی طرف اشارہ ہوتاہے.جیساکہ اَتٰی اَمْرُاللّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ (النحل :۲) وغیرہ بہت سی آیات ہیں.اسی طریق کلام کو یہاں اختیارکیاگیا ہے.اصحاب کہف کی بعثت سے مراد غرض اس آیت میں یہ بتایاگیاہے کہ ہم ایک دن ان قوموں کو جو ا س وقت سورہی ہیں بیدارکریں گے.اس کانتیجہ یہ ہوگاکہ وہ آپس میں یہ سوال کریں گی کہ تم کس قدرعرصہ تک سوتے رہے ہویعنی اب بیدار ہوناچاہیے.چنانچہ صلیبی جنگوں کے وقت ان اقوام میں بیداری پیداہوئی اورانہوں نے اسلام کے خلاف جتھہ بازی کی اور اسلامی ممالک پر حملہ شروع کیا.اصحاب کہف کے عرصہ قیام کی تشریح یہ جوفرمایا ہے کہ لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ.اس سے یہ مراد نہیں کہ ان کوشک تھا کہ ہم دن یادن کاکوئی حصہ سوتے رہے ہیں.بلکہ اس کے معنے عربی محاورہ میں غیرمعین اورلمبی مدت کے بھی ہوتے ہیں.چنانچہ قیامت کے دن کفارکے سوال وجواب میں بھی یہ الفا ظ استعمال ہوئے ہیں.فرماتا ہے قیامت کے دن ہم کفار سے پوچھیں گےكَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ بتائوکہ تم دنیا میں کس قدر عرصہ رہے.اس کے جواب میں کفار کہیں گے لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ.ہم دن یادن کاکچھ حصہ رہے.پس آپ ان سے پوچھئے جو گننے پرمقرر ہیں.(المومنون :۱۱۳،۱۱۴) ان آیات میں سوال کی عبارت سے بھی اوراس جواب سے بھی ظاہر ہے کہ ان کی مرادیہ ہے کہ ایک غیر معین عرصہ تک ہم رہے.یہی معنے اس جگہ ہیں.کہ ایک غیر معین
Page 503
عرصہ تک ہم سوئے رہے.ایک اورجگہ قرآن کریم میں اس عرصہ کو ایک ہزارسال بتایاگیاہے.سورۃ طٰہٰ میں فرماتا ہے يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ زُرْقًا.يَّتَخَافَتُوْنَ۠ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا (طٰہٰ :۱۰۳، ۱۰۴) یعنی جب صورپھونکا جائے گا اورہم مجرموں کو ہوشیا ر کرکے کھڑاکردیں گے جونیلی آنکھ والے رومی قوم کے ہوں گے وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اورکہیں گے کہ تم دس تک سوتے رہے.دس سے مراد دس صدیا ں ہیں یعنی ہزار سال تک سوتے رہے.زُرْقٌ کالفظ جوآیت میں آیا ہے اس کے معنے نیلی آنکھو ں والوں کے ہیں.یوروپین لوگوں کی آنکھیں بوجہ رنگ کی سفیدی کے نیلی ہوتی ہیں اورعرب لوگ رومیوں کو ازرق کہتے تھے یعنی نیلی آنکھوں والے.چنانچہ لغت میں لکھا ہے أزْرَقٌ کے معنے دشمن کے بھی ہوتے ہیں اوراس کی وجہ یہ ہے کہ روم اوردیلم کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں اورعرب لوگ ان کواپنا بڑادشمن سمجھتے تھے اس لئے آہستہ آہستہ اس لفظ کے معنے عربوں میں دشمن کے ہوگئے (اقرب) خلاصہ یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ انہیں شبہ تھا کہ وہ شاید تھوڑی دیر تک اس غفلت کی حالت میں رہے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک لمباغیر معین عرصہ اس حالت میں رہے ہیں.سورۃ طٰہٰ میں اس عرصہ کی مقدار ایک ہزارسال بتائی ہے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ایک ہزار سال کاعرصہ شمارکیاجائے توحساب یوں بنتاہے.رسول کریم صلعم کی پیدائش مطابق شمار سرولیم میور ۵۷۰ ء میں ہوئی.(لائف آف محمدباب ۱ صفحہ ۵) دعویٰ نبوت چالیس سال بعد ہوا.پس دعویٰ کی تاریخ ہوئی ۶۱۱ء.اس میں ہزار سال جمع کئے جائیں تو۶۱۱ ۱ ء یا ۶۱۲ ۱ء بنتے ہیں.اوریہی وہ تاریخیں ہیں جن میں ہندوستان میں انگریزوں کے قدم جمے.۶۱۱ ۱ ء میں مغلیہ حکومت نے خلیج بنگا ل میں کام کرنے کی انگریزوں کواجازت دی.اور ۱۶۱۲ ء میں سُورتؔمیں پہلا کارخانہ کھولنے کی اجازت دی (مارچ آف مین MARCH OF MAN مطبوعہ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکاسوسائٹی )دنیاجانتی ہے کہ یورپ کی ترقی اوراس کے دنیامیں پھیلنے کی یہ پہلی بنیاد تھی.یورپ نے انگریزوں کے نقش قدم پر اوران کے سہار ے پر ترقی کی ہے.اورانگریزوں کی ترقی کا رازہندوستان میں ان کاوارد ہوناہے.ہندوستان ہی میں قد م جمنے پر انہوں نے دوسرے ایشائی ممالک پراورافریقہ پر قبضہ کیا.اوران کے اس طرح اقتدار حاصل کرنے پر دوسری یوروپین اقوام نے دنیا میںترقی کی.شاید کوئی کہے کہ ذکر تو رومیوں کاتھا انگریزوں کاان امو رسے کیا تعلق ؟تواس کا جواب یہ ہے کہ یورپ کاموجودہ تمدن رومی اثر کاہی نتیجہ ہے اورسب یورپ روم کاشاگرد ہے اوراسی کی تہذیب کی یاد گار.اوریو رپ میں
Page 504
عیسائیت بھی روم کےہی ذریعہ سے قائم ہوئی ہے اس لئے شاخوں کاکام جڑ ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے.اَزْکیٰ کے معنے اَصْلَحَ کے ہوتے ہیں.یعنی مناسب حال.اوراس کے معنے اعلیٰ درجہ کے بھی ہیں یورپ کی قوموں کے پھیلنے کی بڑی وجہ یہی ہوئی ہے کہ ان کے ملکو ں میں غلہ کافی نہیں ہوتا اورو ہ غلے اور مصالحے ایشیا سے لے جاتے تھے.پہلے عربوں کی معرفت وہ چیزیں خریدتے تھے.لیکن جب ہندوستان کاراستہ دریافت ہوگیاتوانہوں نے براہ راست ان اشیاء کی تجارت اپنے ہاتھ میں لے لی.اورآہستہ آہستہ دوسری چیزوں کی تجارت بھی ان کے ہاتھ میں آگئی.طَعَامٌ کے معنے اس جگہ پکے ہوئے کھانے کے نہیں.عربی زبان میں طعام ہرکھانے کی چیز کو کہتے ہیں.خصوصاً گند م کو.اورجب تک امریکہ نے گندم کی پیداوار میں کوشش نہیں کی جوبالکل قریب زمانہ کی بات ہے دوسو سال تک یورپ کو ہندوستان ہی گند م مہیاکرتارہاہے.گویا انہوں نے اس غلہ خریدنے والے کو ہدایت کی کہ چونکہ ہم نے اس غلہ کو ذخیرہ کرنا ہے اوردیر تک جمع رکھنا ہے اس لئے مناسب طعام دیکھ کرلانا.یہ جوفرمایا ہے وَ لْيَتَؔلَطَّفْ یہ مغربی قوموں کاخاصہ ہے.ان کے باہر جانے والے افسروں کوخاص ہدایت ہوتی ہے کہ و ہ بہت میٹھے طورپر باتیں کریں اورتاجربھی ایسے میٹھے رہتے ہیں کہ لوگوں میں جوش پیدا نہیں ہوتا.وَ لَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا اس آیت میں گواَحَدًا کالفظ آیا ہے.اورضمائربھی مفرد کے استعمال ہوئے ہیں.لیکن میرے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی کابھجوایاجانایہاں مراد ہو.قرآن کریم میں حضرت آدم کے قصے میں ابلیس کا ذکر آتا ہے اورسب باتیں اسی کومخاطب کرکے کہی گئی ہیں.لیکن دوسرے مقامات پرا س کے ساتھ اور جماعت بھی تسلیم کی گئی ہے.جیسے کہ فرماتا ہے بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اسی طرح بعض دوسرے مقامات پر ابلیس کی ذریت کابھی ذکر کیا ہے.پس گولفظ اَحَدَ کُمْ کااستعمال ہواہے مگر مراد یہ ہے کہ اپنے میں سے بعض کو سوداخریدنے کے لئے بھجوائواورمفردکالفظ میرے نزدیک اس نظام پردلالت کرنے کے لئے رکھا گیاہے کہ ایک نظام کے ماتحت جائیں اورذمہ دار اورجوابدہ ایک ہی شخص ہو.کسی کوتمہاراعلم نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ اپنے وجود کومحسوس نہ ہونے دینا اور یہ ظاہر نہ ہونے دیناکہ تمہاری قوم کی نیت ان ممالک میں نفو ذ پیداکرنے کی ہے.بلکہ ایسی طرح معاملہ کرنا کہ تمہاری آمد کی اغراض کو لوگ تاڑ نہ جائیں اور تمہارے اصلی منشاء کو نہ پہچانیں.
Page 505
اوراس میں مشورہ دینے والوں کے لئے اورجن کومشورہ دیاگیا ہے ان کے لئے جوجمع کاصیغہ استعمال کیاگیاہے اس سے میرے نزدیک اس طرف اشارہ ہے کہ یہ وفدبھیجے والی ایک کمپنی ہوگی کوئی بادشاہ یہ کام نہ کرے گا.چنانچہ انگریزی وفد جوہندوستان آیا.یافرانسیسی وفودجوآئے یہ سب کمپنیوں کی طرف سے تھے.ان کاآقاکوئی ایک فرد نہ تھا بلکہ کمپنیا ں تھیں(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ India).اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ (کیونکہ)اگر وہ تم پر غلبہ پالیں تویقیناً تمہیں سنگسارکردیں گے یا(جبراً )تمہیں واپس اپنے مذہب میں داخل کرلیں مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوْۤا اِذًا اَبَدًا۰۰۲۱ گے اوراس صورت میں کبھی (بھی )کامیاب نہیں ہوگے.حلّ لُغَات.یَظْھَرُوْاعَلَیْکُمْ ظَھَرَ (یَظْھَرُ عَلَیْہِ):غَلَبَہٗ.اس پر غالب آیا.ظَھَرَ فُلَانٌ عَلٰی سِرِّہٖ: اِطَّلَعَ عَلَیْہِ.کسی بھید پرمطلع ہوا(اقرب) یَرْجُمُوْکُمْ:یَرْجُمُوْکُمْ رَجَمَ سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے.رجم کے معنے کے لئے دیکھو سورۃ حجرآیت نمبر ۱۸.رَجِیْمٌ رَجَمَ میں سے ہے.اوررَجَمَہٗ رَجْمًا کے معنے ہیں :رَمَاہُ بِالْحِجَارَۃِ.اس پر پتھر برسائے.قَتَلَہُ اس کو قتل کیا.قَذَفَہُ.اس پر تہمت لگائی.لَعَنَہٗ.لعنت کی.شَتَمَہُ.گالی دی.ھَجَرَہُ.چھوڑ دیا.ترک کردیا.اَلْقَبَرَ :عَلَّمَہُ.قبرپر نشان لگایا.جَاءَ یَرْجُمُ کے معنے ہیں.اِذا مَرَّ وَھُوَ یَضْطَرمُ فِی عَدْوِہٖ.تیزی سے دوڑتا ہوا گزرا.الرَّجُلُ:تَکَلَّمَ بِالظَّنِ ظنی بات کی.(اقرب) الرَّجْمُ اَیْضًا اَنْ یَّتَکَلَّمَ بِالظَّنِ.رجم کے معنے غیر یقینی بات کرنے کے بھی ہیں جیسے آیت رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ میں رجم کے معنے ہیں.لَایُوْقَفُ عَلیٰ حقِیْقَتِہٖ.یعنی بات کی حقیقت سے واقف نہ تھا.اِسمُ مایُرجَمُ بہٖ جس چیز سے ماراجائے اس کو بھی رجم کہتے ہیں.اس کی جمع رُجُومٌ آتی ہے(اقرب) الرِجَامُ:اَلْـحِجَارَۃُ.رِجَامٌ کے معنے پتھروں کے ہیں.اوراَلرَّجْمُ کے معنے ہیں.اَلرَّمْیُ بِالرِّجَامِ کسی کو پتھر مارنا.جب کسی پر پتھرائو کیاجائے تو رُجِمَ بصیغہ مجہول استعمال کرتے ہیں.وَیُسْتَعَارُ الرَّجْمُ لِلرَّمْیِ بِالظَّنِّ.
Page 506
اوراستعارۃً رجم کالفظ خیالی اورغیر یقینی بات کے کرنے پر بھی بولاجاتاہے.وَالتَّوَھُّمِ وَلِلشَّتْمِ وَالطَّرْدِ.نیز یہ لفظ وہم سے بات کرنے.گالی دینے اوردھتکارنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتاہے.اور اَلشَّیْطَانُ الرَّجِیْمُ کے معنے ہیں اَلْمَطْرُوْدُعَنِ الْخَیْرَاتِ.نیکیوں سے دور خوبیوں سے محروم و عاری.وَعَنْ مَنازِلِ الْمَلَأِ الْاَعْلیٰ فرشتوں کے مقامات سے دورکیاہوا(مفردات)اورمجمع البحارمیںہے وَرُجُوْمًا لِلشَّیَاطِیْنِ وَعَلَامَاتٍ ھُوَجَمْعُ رَجْمٍ مَصْدَرٌ سُمِّیَ بِہٖ.رجم کالفظ مصدر ہے جو اسم کے طور پر استعمال ہواہے.اور رُجُوْمٌ اس کی جمع ہے.وَیَجُوْزُکَوْنُہُ مَصْدرًا لَاجَمْعًا اوریہ بھی ہو سکتاہے.کہ رجوم مصدرہونہ کہ جمع.ومَعْنَاہُ اَن الشَّھَبَ الَّتِیْ تَنْقَضُّ مُنْفَصِلَۃً مِنْ نَارِ الْکَوَاکِبِ وَنُوْرِھَا لَااَنَّھُمْ یُرْجَمُوْنَ بِاَنْفُسِ الْکَواکِبِ لِاَ نَّہَا ثَابِتَۃٌ لَاتَزُوْلُ کَقَبَسٍ تُؤْخَذُ مِنْ نارٍ.یعنی وہ شہب جو ستاروں کی آگ سے علیحدہ ہوکر ٹوٹتے ہیں.وہ خود ستارے نہیں ہوتے.بلکہ ستاروں سے روشنی گرتی ہے کیونکہ ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں اورشہب کاگرنا اسی طرح ہوتاہے جیسے ایک چنگاری آگ سے لی جاتی ہے.وَقِیْلَ اَرَادَ بِالرُّجُوْمِ الظُّنُوْنُ الَّتِیْ تُحْزَرُوَمِنْہُ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ.اوربعض محققین نے یہ کہاہے کہ رُجُوْمٌ سے مراد وہ خیالات ہیں جو اپنے قیاس سے بغیر دلیل کے انسان بنالیتا ہے اورانہی معنوں میں قرآن میں لفظ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِاستعمال ہوا ہے.یعنی وہ غیب کے متعلق صرف اندازے لگاتے ہیں.الملّۃ اَلْمِلَّۃُ اس کے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر ۱۴.اَلْمِلَّۃُ: اَلشَّرِیْعَۃُ اَوِ الدِّیْنُ.شریعت اور دین کو ملت کہتے ہیں.وَقِیْلَ الْمِلَّۃُ وَالطَّرِیْقَۃُ سَوَاءٌ.بعض کہتے ہیں کہ ملت اور طریقہ ہم معنے لفظ ہیں.وَھِیَ اِسْمٌ مِنْ اَمْلَیْتُ الْکِتٰبَ ثُمَّ نُقِلَتْ اِلَی أُصُوْلِ الشَّرَائِعِ بِاِعْتِبَارِ اَنَّہَا یُمْلِیْہَا النَّبِیُّ اور ملت اسم ہے جو اَمْلَیْتُ الْکِتَابَ کے محاورہ سے ماخوذ ہے پھر وہ شریعت کے اصول کے معنوں میں استعمال ہونے لگا.کیونکہ شریعت کے اصول نبی لکھاتا ہے.وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَی الْبَاطِلِ کَالْکُفْرِ مِلَّةٌ وَاحِدَۃٌ اور کبھی یہ لفظ جھوٹے مذہبوں پر بھی بولا جاتا ہے.جیسے اَلْکُفْرُ مِلَّۃٌ وَاحِدَۃٌ کے محاورہ سے ظاہر ہے.وَلَاتُضَافُ اِلَی اللہ ِوَلَا اِلٰی اُحَادِ الْاُمَّۃِ.اور یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوتا.اور نہ امت کے کسی فرد کی طرف.یعنی دِیْنُ اللہِ تو کہہ سکتے ہیں مگر مِلَّۃُ اللہِ نہیں کہہ سکتے.اسی طرح قوم کی ملت کہیں گے زید یا بکر کی ملت کا لفظ نہیں بولیں گے.(اقرب) تفسیر.اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ان اقوام کو جن کی طرف تم وفد بھیج رہے ہو تمہاراعلم ہوگیا (ظَھَرَ عَلٰی
Page 507
السِّرِّکے معنے ہوتے ہیں اس کوراز معلوم ہوگیا )یایہ کہ اگرجھگڑاہوگیا اورقدم جمانے سے پہلے ان سے لڑائی ہوگئی اور تم مغلوب ہوگئے تووہ تم کو اپنے ملکوں سے نکال دیں گے.(رجم کے معنے دھتکار دینے کے بھی ہوتے ہیں) (اقرب)یااگرنہ نکالیں توتم کو مجبور کریں گے کہ ان کے مذاہب میں داخل ہوجائو اوراگر ایساہوایعنی تم کو انہوں نے ملک سے نکال دیا.یایہ کہ تم کواپنے مذاہب میں داخل کر دیا.توتمہارازورہمیشہ کے لئے ٹوٹ جائے گا اورپھر کبھی ترقی نہ کرسکو گے.چنانچہ دیکھ لوکہ یوروپین قومیں سیاسی اغراض کی وجہ سے ہمیشہ عیسائی مذہب کی مدد کرتی ہیں اور دوسری اقوام کے خیالات اپنے اند رپھیلنے سے روکنے کے لئے ہر قسم کی تدابیراختیار کرتی رہتی ہیں.وَ كَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اور اسی طرح ہم نے (لوگوں کو )ان (کے حالات) سے آگاہ کیا ہے تاانہیں معلوم ہو کہ اللہ(تعالیٰ)کاوعدہ اَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا١ۗۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ پوراہوکر رہنے والا ہےاور(یہ بھی )کہ اس (موعودہ)گھڑی (کے آنے)میں کچھ بھی شک نہیں (اوراس وقت کو بھی اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا١ؕ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ١ؕ یاد کرو)جب و ہ اپنے کا م کے متعلق آپس میں گفتگوکرنے لگے اورانہوں نے (ایک دوسرے سے)کہا (کہ)تم ان قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰۤى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ (کے رہنے کے مقام )پرکوئی عمارت بنائو.ان کارب ان( کے حال)کوسب سے بہترجانتاتھا.(آخر)جنہوں مَّسْجِدًا۰۰۲۲ نے اپنے قول میں غلبہ حاصل کرلیا انہوں نے کہا(کہ)ہم(تو)ان (کے رہنے کے مقام )پر مسجد (ہی )بنائیں گے حلّ لُغَات.اَعْثَرْنَا اَعْثَرْنَا اَعْثَرَ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے اورأَعْثَرَ فُلَانًا عَلَی السِّرِّوَغَیْرِہِ کے معنے ہیں : اَطْلَعہٗ.اس کو بھیدوں پر مطلع کیا.اَعْثَرَ فُلَانًا عَلٰی اَصْحَابِہِ : دَلَّہٗ عَلَیْہِم.کسی کو اپنے دوستوںکے متعلق آگاہ کیا.اَعْثَرَبِہِ عِنْدَالسُّلْطَانِ :قَدَحَ فِیْہِ وَ طَلَبَ تَوْرِیَطَہُ وَاَنْ یَقَعَ فِی عَاثُوْرٍ.بادشاہ کے ہاں اس پر
Page 508
جرح کی اوراس کے مرتبہ کو گرایا (اقرب) الساعۃالسَّاعَۃُ کے لئے دیکھو سور ۃ نحل آیت نمبر ۶۲.رَیْب رَیْبٌ رَابَ(یَرِیْبُ رَیْبًا)کامصدرہے اوررَابَ کے معنے ہیں اَوْقَعَہٗ فی الرَّیْبِ واَوْصَلَ اِلَیْہِ الرِّیْبَۃَ.اسے شک میں ڈالا نیز اَلرَّیْبُ کے معنے ہیں اَلظَّنَۃُ وَالتُّھْمَۃُ.ظن.تہمت.الشَّکُّ.شک.اَلحَاجَۃُ.حاجت (اقرب) یتنازعون:یَتَنَازَعُوْنَ تَنَازَعَ سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے اورتنازَعُوْا کے معنے ہیں اِخْتَلَفُوْا.انہوں نے آپس میں اختلاف کیا.تَنَازَعُوْافِی الشَّیْءِ:تَخَاصَمُوْا.کسی چیز میں جھگڑاکیا.(اقرب) بنیانًا.بُنْیَانًا بَنٰی کامصدر ہے اوربَنَاہُ (یَبْنِیْہِ بُنْیَانًا)کے معنے ہیں:نَقِیْضُ ھَدَمَہ.کسی چیز کوبنایا.بَنَی الْاَرْضَ:بَنَی فِیْھَادارًاوَنَحْوَھَا.کسی زمین میں مکان بنایا (اقرب) المسجد اَلْمَسْجِدُ وَ الْمَسْجَدُ:اَلْمَوْضِعُ الَّذِیْ یُسْجَدُ فِیْہِ.وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے.کُلُّ مَوْضِعٍ یُتَعَبَّدُ فِیْہِ.ہروہ جگہ جہاں عبادت کی جائے.وَقِیْلَ اِنَّ الْمَسْجِدَ بِالْکَسْرِ اِسْمٌ لِمَوْضِعِ الْعِبَادَۃِ یُسْجَدُ فِیہِ اَوْلَمْ یُسْجَدْ.اوربعض نے کہاہے کہ مَسْجِدٌ(بِکَسْرِجِیْمٍ)مطلق عبادت کی جگہ کو کہتے ہیں.خواہ اس میں سجدہ کیاجائے یانہ.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ یہ اقوام جو عرصہ تک دنیاسے الگ رہی تھیں.اس طرح پھر دنیاسے روشناس ہوگئیں اوردنیا کومعلوم ہوگیا کہ مسیحی اقوام کے آخری ایام میں غلبہ کی جو خبر ہم نے دی تھی و ہ بالکل سچی تھی اوریہ کہ وہ موعود گھڑی جس سے ہم ڈرارہے تھے ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی.عیسائیوں میں مردوں کے نام گرجے بنانے کی عادت اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ سے پھر اصحاب کہف کی ابتدائی حالت کاکچھ ذکرفرمایااوران کی ایک علامت بتائی.فرماتا ہے کہ اس قوم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ان میں یہ عادت ہے کہ اپنے وفات یافتوں کے نام پر مساجد یعنی معابد بناتے ہیں.جوان کے بزرگ گذرے ہیں ان کی یاد میں ہرجگہ گرجے بناتے ہیں.چنانچہ دیکھ لومسیحی ہی ایک قوم ہے جن میں بزرگو ںکے نام پر گرجے بنائے جاتے ہیں.مسلمانوں کی کوئی مسجد کسی بزرگ کے نام پر نہیں بنائی جاتی اورنہ یہود میں ایساہوتاہے.مگر مسیحیوں کے ہزاروں گرجے بزرگوں کی یاد میں ہیں بلکہ گرجوں میں یہ لوگ مردوں کو دفن بھی کرتے ہیں.ابتدائی اصحاب کہف کی یاد گارمیں بھی کیٹاکومبزمیں بہت سے گرجے بنے ہو ئے ہیں(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Catacombs).
Page 509
سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ١ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ وہ (لوگ جو حقیقت حال سے بےخبر ہیں ضرور)غیب کے متعلق نشا نہ بازی کرتے ہوئے (کبھی)کہیں گے (کہ و ہ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ١ۚ وَ يَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّ صرف)تین(آدمی)تھے جن کے ساتھ چوتھاان کاکتاتھا اور(کبھی )کہیں گے (کہ وہ )پانچ تھے جن کے ساتھ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ١ؕ قُلْ رَّبِّيْۤ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ چھٹا ان کاکتاتھا.اور(ان میں سے بعض یوں بھی )کہیں گے (کہ وہ )سات تھے اوران کے ساتھ آٹھواں ان اِلَّا قَلِيْلٌ١۫۬ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا١۪ وَّ لَا کاکتاتھاتو(انہیں )کہہ (کہ)ان کی(صحیح)گنتی کواللہ (تعالیٰ ہی)بہترجانتاہے (اور)تھوڑے لوگوں کے سوا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًاؒ۰۰۲۳ انہیںکوئی نہیںجانتا.پس توان کے متعلق مضبوط بحث کے سواکوئی بحث نہ کر اوران کے بارہ میں ان میں سے کسی سے حقیقت حال دریافت نہ کر.حلّ لُغَات.رَجْمًابِالْغَیْبِ.اَلرَّجْمُ:اَنْ یُتَکَلَّمَ بِالظَّنِ.یُقَالُ ’’رَجْمًا بِالْغَیْبِ‘‘اَیْ لَا یُوْقَفُ عَلٰی حَقِیْقَتِہِ.رجم کے معنے ظنی طورپر بات کرنے کے ہیں.اوررَجْمًۢا بِالْغَيْبِ انہی معنوں میں ہے کہ اس نے بات توکی لیکن اس کی حقیقت سے بے خبرتھا.مزید تشریح کے لئے دیکھو سورہ حجرآیت نمبر ۳۰یا الکہف آیت نمبر ۲۰.تُمارِ:مَارَاٰہُ(مُمَارَاۃً وَمِرَاءً )کے معنے ہیں جَادَلَہُ وَنَازَ عَہٗ.اس نے اس سے جھگڑاکیا.وَلَاجَّہَ وَطَعَنَ فِیْ قَوْلِہٖ تَزْیِیْفًالِلْقَوْلِ وَتَصْغِیْـرًالِلْقَوْلِ.اس نے نہایت سختی سے جھگڑاکیااورمدمقابل کی بات کوساقط قرار دیتے ہوئے طعنہ زنی کی اورکلام کی اہانت کی (اقرب) لَاتَسْتَفْتِ لَاتَسْتَفْتِ اِسْتَفْتٰی سے نہی کاصیغہ ہے اوراِسْتَفْتٰی فُلَانٌ الْعَالِمَ فِی مَسْئَلَۃٍ
Page 510
(اِسْتِفْتَاءً) کے معنے ہیں سَأَلَہٗ اَنْ یُفْتِیَہٗ فِیْھَا.اس نے کسی عالم سے چاہاکہ وہ ا س کے متعلق اسے واقفیت بہم پہنچائے.(اقرب) تفسیر.اصحاب کہف کی گنتی کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اس آیت میں پھر ابتدائی اصحاب کہف کی نسبت ایک اوربحث کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی ان کو تین بتاتاہے کوئی چار کوئی پانچ ،مگر یہ سب ظنی باتیں ہیں اورکوئی کہتاہے کہ سات ہیں آٹھواںان کاکتاہے.بعض نے اس سے یہ نتیجہ نکالاہے کہ سات تھے.کیونکہ پہلے اعداد کے ساتھ توفرمایا یہ ظنی باتیں ہیںاوراس آخر ی تعداد کو بعد میں بیان کیا ہے معلوم ہوایہ قول درست ہے.حالانکہ یہ قول بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا.بلکہ دوسروں کی طرف منسوب کیاہے اوراس کے بعد فرمایا ہے کہ توان سب لوگوں سے کہہ دے کہ اللہ ان کی گنتی کوجانتاہے.اگریہ آخری گروہ صحیح اندازہ بیان کرنے والاہوتا توان کو یہ کیوں کہاجاتا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گنتی کوجانتاہے.پھرتویہ کہناچاہیے تھا کہ تُوان لوگوں سے کہہ دے کہ تمہارابیان صحیح ہے.پس درحقیقت اس قول والوں کی بھی تردید کی گئی ہے کیونکہ اصحاب کہف پانچ سات نہ تھے.بلکہ و ہ تومختلف اوقات میں غاروں میں چھپتے رہے اورہزاروں کی تعداد میں تھے.پس اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواان کی گنتی کوئی نہیں جانتا.مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ.کے یہ معنے نہیں کہ تھوڑے سے لوگوںکو ان کی گنتی معلوم ہے.بلکہ یا تواس کامطلب یہ ہے کہ ان کی گنتی کوئی بھی نہیں جانتا.کیونکہ قلیل کالفظ عربی میں اسی طرح نفی کے لئے آتاہے جس طرح انگریزی میں فیو FEW کالفظ نفی کے لئے آتاہے.چنانچہ کہتے ہیں قَلِیْلٌ مِنَ الرِّجَالِ یَقُوْلُ ذَالِکَ اوراس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہتا(اقرب)یا پھر ا س آیت میں چونکہ گنتی کالفظ نہیں اس آیت کایہ مطلب ہے کہ اصحاب کہف کی حقیقت کو تھوڑے آد می جانتے ہیں.یعنی وہ جو صحیح تاریخ سے واقف ہیںوہ جانتے ہیں کہ یہ ابتدائی مسیحی لو گ تھے جو کیٹاکومبز میں چھپاکرتے تھے.باقی لوگ ان کے بار ہ میں مختلف قصوں سے دھوکاکھارہے ہیں.چنانچہ ان قلیل کے علم کا ہی نتیجہ ہے کہ آخر ان کی اصل حقیقت ظاہرہوگئی.آگے فرمایا کہ ان کے بارہ میں سوائے اصولی بات کے اورکوئی بات نہ کر و.یعنی تفاصیل دنیاکومعلوم نہیں ہیں.پس صرف اصو لی باتیں کرو اورتفاصیل میں نہ پڑو.اوریہ کہہ کرکہ لوگوں سے ان کے بار ہ میںسوال نہ کرویہ بتایا ہے کہ تاریخ کایہ حصہ مٹ گیاہے کوئی بھی پور ی تفصیل اس واقعہ کی نہیں بتاسکتا.ا س لئے اگر تفصیلی معلومات حاصل کرناچاہو گے توغلطی کروگے.مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس حکم کے باوجود کتے کارنگ اوراس کاقد تک یہود
Page 511
ونصاریٰ سے پوچھنے کی کوشش کی اوراس طرح تفاسیر میں بے ثبوت روایات کاوہ ذخیرہ جمع کردیا کہ اسے پڑ ھ کررونا آتاہے.وَ لَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًاۙ۰۰۲۴ اورتُوکسی بات کے متعلق (دعویٰ سے)ہر گز نہ کہہ (کہ)میں کل یہ (کام)ضرور کروں گا.سوائے اس( صورت ) اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ١ٞ وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ کے کہ اللہ( تعالیٰ کسی امر کے متعلق ایسا کہنا )پسند کرے.اورجب (کسی وقت)توبھول جائے تو(یاد آجانے پر ) وَ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ اپنے رب کو یاد (کیا )کر اور (لوگوں سے )کہہ دے (کہ مجھے کامل )امید ہے کہ میرار ب مجھے اس (راستہ ) مِنْ هٰذَا رَشَدًا۰۰۲۵ پرچلائے گا جوہدایت پانے کے لحاظ سے اس ( میرے موجود ہ طریق )سے (بھی تکمیل کے )زیادہ قریب ہوگا.حلّ لُغَات.الغد اَلْغَدُ کے معنے ہیں اَلْیَوْمُ الَّذِیْ یَاْتِیْ بَعْدَ یَوْمِکَ عَلٰی اَثَرٍثُمَّ تَوَسَّعُوْا فِیْہِ حَتّٰی اُطْلِقَ عَلَی الْبَعِیْدِ الْمُتَرَقَّبِ.کل.دوسرادن.آئندہ زمانہ کاکوئی دن جس کا انتظار ہو(اقرب) تفسیر.اس آیت میں پھر اس قوم کی ترقی کے زمانہ کے متعلق ایک خبر دی ہے.اورو ہ یہ کہ اس قوم کے مقابلہ پر دعویٰ نہ کرنا اوریہ نہ کہنا کہ بس ہم کل ان کوتباہ کردیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان کے متعلق کوئی خبردے یعنی الہام سے بتائے کہ ان سے اب فلاں سلوک ہونے والا ہے.بعض لوگوں نے اس آیت کے یہ معنے کئے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ کوئی بات بغیر اِنْ شَآءَ اللہُ کے نہ کہاکرو.اورا س حکم کے متعلق بعض نہایت افسوسناک روایات نقل کی ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہتک ہے (ابن کثیر والقرطبی زیر آیت ھٰذا).حالانکہ آیت کے الفاظ صاف بتارہے ہیں کہ یہاںاِنْ شَآءَ اللہُ کہنے کاکوئی ذکر نہیں.اگر وہ مضمون ہوتاتو الفا ظ یوں چاہیے تھے اِلَّا اَنْ تَقُوْلَ اِنْ شَآئَ اللہُ.مگر یہاں تو
Page 512
فقرہ کے کہنے کاحکم نہ دے.پس آیت کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ اس قوم کامقابلہ مسلمان اپنی طاقت سے نہ کرسکیں گے.بلکہ وہ ان کامقابلہ کرسکے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے ان کے مقابلہ کے لئے کھڑاکرے گا.مسلمانوں کی موجودہ حالت کی طرف اشارہ اس آیت میں مسلمانوں کی اس وقت کی حالت کی طرف اشارہ ہے جب وہ ان اقوام کی ترقی کو دیکھ کر جوش میں آئیں گے اوران کامقابلہ کرنے کی تیار یاں کریں گے.لیکن وہ اس میں کامیا ب نہ ہوںگے.دوسرے اس زمانہ کے مسلمانوں کی حالت بتائی ہے کہ وہ کام کی بجائے کَل کی امیدوں پر آجائیں گے اورہمیشہ یہ کہیں گے کہ ہم کَل یہ کردکھائیں گے یعنی قوت عملیہ مفقود ہوجائے گی اورڈراوے اوردھمکیاں رہ جائیں گی اورہمیشہ کل کالفظ بولتے رہیں گے کبھی وہ کل آج کی صورت اختیارنہ کرے گا.چنانچہ دیکھ لوکہ اس زمانہ میں یہ صداقت ساری مسلمان اقوام کے اعمال سے ا س طرح ظاہر ہورہی ہے کہ افسوس بھی آتاہے اورتعجب بھی.وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ کہہ کر یہ بتایا کہ اگر کبھی جوش میں آکر ان قوموں کے مقابلہ کاخیال تمہارے دل میں پیداہو تواللہ تعالیٰ کے وعدوں کویاد کرلیا کرو کہ خدا تعالیٰ کاوعدہ ہے کہ ایک دن مسلمانوں کو ان کے حملہ سے بچائے گااورغیب سے مسلمانو ں کی نجات کے ساما ن پیداکر ےگا.اس لئے الٰہی تدابیر کے سوادوسری تدابیر کاخیال دل سے نکال دینا چاہیے.مسلمانوں کو نصیحت کہ خدا کے فضل سے ہی اس قوم کے فتنوں سے بچو گے وَ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا میں بھی یہ سبق دیا کہ تمہاری ظاہر ی تدابیر توسینکڑوں سالوں میں ان اقوام کو تباہ نہیں کرسکتیں.لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت جلد ایسے سامان پیداکردے گا کہ تم ان فتنوںسے محفوظ ہوجائو.افسوس مسلمانوں نے اس نصیحت سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اوریوروپین اقوام کے مقابل پر با ربار جہاد کے اعلانات کرکے اسلام کے رعب کو او ربھی مٹادیا.بلکہ جن خیر خواہوں نے ان کو اس قسم کی باتوں سے روکا ان کواسلام کادشمن قرار دیا اوریہ نہ سمجھے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف بلاتے ہیں وہ اسلام کے دشمن نہیں بلکہ وہ دشمن ہیں جوباوجود قرآن کریم کے منع کرنے کے پھر بھی غلط طریقہ کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں.
Page 513
وَ لَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَ ازْدَادُوْا اور(یہ بھی کہتے ہیں کہ )وہ (اس)اپنی وسیع پہاڑی پنا ہ گاہ میں تین سوسال تک رہے تھے اور(اس عرصہ پر ) تِسْعًا۰۰۲۶ نو(سال)انہوں نے اوربڑھائے تھے.تفسیر.اصحاب کہف کے قیام غار کے عرصہ تین سو نو سال کا ثبوت اس آیت میں قدیم اصحاب کہف کی مصیبتوں کا زمانہ بتایاہے جس زمانہ تک کہ ان پر ظلم ہوتے رہے اوران کو بار بار غاروں میں جاکر چھپنا پڑا.فرماتا ہے کہ و ہ تین سونوسال کا زمانہ ہے.تاریخ سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے.کیونکہ یہ مصائب کا زمانہ حضرت مسیح ؑ کے صلیب پانے کے وقت سے شرو ع ہوتاہے اورپوراامن کانسٹنٹائن (بانی قسطنطنیہ)کے عیسائی ہوجانے کے وقت حاصل ہواہے.کانسٹسٹائن ۳۳۷ ء میں عیسائی ہواہے جیسا کہ اوپر لکھاجاچکا ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Constantine) بظاہر یہ زمانہ قرآنی بیان کے خلاف معلوم ہوتاہے.لیکن جب ہم مسیحی تاریخ پر غورکرتے ہیں تومعلوم ہوتاہے کہ یہ تاریخ غلط ہے.مسیحی کیلنڈر کی غلطی اصل سال جس میں کانسٹنٹائن بادشاہ روم عیسائی ہوا ۳۰۹ ء ہے اوراس کاثبوت یہ ہے کہ خود مسیحی جغرافیہ نویسوں نے تسلیم کیاہے کہ مسیحی کلنڈر میں غلطی ہوگئی ہے چنانچہ آرچ بشپ اشرز (USHERS) نے اپنی کتاب علم تاریخ(CHRONOLOGY)میں اورڈاکٹر کٹو KITTO نے اپنی کتاب ’’ڈیلی بائبل السٹریشنز ‘‘ میں ثابت کیاہے کہ جوتاریخ مسیحی کلنڈر میں واقعہ صلیب کی دی گئی ہے وہ غلط ہے اوریہ غلطی ۵۲۷ ء میں لگی ہے.حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ سے صرف چار یاچھ سال پہلے مسیح پیداہوئے تھے.پس اس وقت ان کی عمر صرف چار سے چھ سال تک کی ہوتی ہے لیکن وہ صلیب پر تنتیس سال کی عمر میں لٹکائے گئے تھے.اب اس بیان کے مطابق اگرچار اور چھ کی اوسط نکالی جائے توپانچ بنتی ہے.چونکہ مسیح کوصلیب تینتیسویں سال میں دیاگیاتھا اس لئے مسیحی سن میں سے اٹھائیس سال منہاکرنے پڑیں گے کیونکہ مسیحی کلنڈر سے اٹھائیس سال بعد صلیب کاواقعہ ہواہے.اب اٹھائیس سال کو ۳۳۷ ء میں سے نکالوتوپورے ۳۰۹ ء سال ہوتے ہیں.یہ تومسیحی روایات کوصحیح تسلیم کرکے ہے ورنہ اگر یہ شہادت نہ بھی ہوتب بھی قرآن کریم جس کی سب خبریں بائبل کے مقابل میں صحیح ثابت ہوتی ہیں اس کی
Page 514
بات کوبہرحال مقد م رکھناہوگا.اس آیت میں بتایاگیاہے کہ لمبے مصائب سے گھبرانانہیں چاہیے.ہم سے پہلے مسیحی جماعت کو تین سونوسال تک دکھ دئیے گئے.لیکن انہوں نے صبرسے کام لیا اورآخر اس صبر کانہایت شیریں پھل کھایا.پس تم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے کام میں لگے رہناچاہیے اوراستقلا ل سے مصائب کامقابلہ کرناچاہیے.قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا١ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ تو(انہیں )کہہ(کہ )جو(عرصہ)و ہ ٹھہرے رہے تھے اسے اللہ (تعالیٰ)بہترجانتاہے.آسمانوں اورزمین کاغیب اَبْصِرْ بِهٖ وَ اَسْمِعْ١ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ١ٞ وَّ لَا (کاعلم )اسی کے لئے (مسلّم )ہے.و ہ خوب ہی دیکھنے والا اورخوب ہی سننے والا ہے.ان(لوگوں )کا اس کے يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا۰۰۲۷ سواکوئی بھی مددگار نہیں ہے.اوروہ اپنے حکم (اوراپنے فیصلوں )میں کسی کو (اپنا )شریک نہیں بناتا.حل لغات.اَلْغَیْبُ غَیْبٌ غَابَ کامصدر ہے اورغَیْبٌ کے معنے کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر ۱۰.غَابَتِ الشَّمْسُ وَغَیرُھَا: اِذَا اسْتَتَرَتْ عَنِ الْعَیْنِ غَابَ کا لفظ سورج کے لئے یا کسی اور چیز کے لئے اس وقت بولتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوجاوے.یا کوئی اور چیز آنکھوں سے اوجھل ہوجائے.وَاسْتُعْمِلَ فِیْ کُلِّ غَائِبٍ عَنِ الْحَاسَۃِ جو بات حواس سے بالا اور پوشیدہ ہو اس پر بھی غیب کا لفظ اطلاق پاتا ہے.اور شہادۃ کا لفظ غیب کے بالمقابل بولا جاتا ہے.(مفردات) پس غیب اور شہادت کے دو معنی ہیں.(۱) شہادۃ جو لوگ ظاہر کرتے ہوں.اور غیب جسے وہ چھپاتے ہوں.(۲)جو حواس ظاہری سے معلوم ہوسکے وہ شہادت ہے اور جو باتیں حواس سے بالا اور پوشیدہ ہیںوہ غیب ہے.اَبْصِرْبِہِ واَسْمِعْ:دونوں فعل تعجب ہیں.یعنی وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے.اور کیا ہی خوب سننے والا ہے.تفسیر.قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا کہہ کر بتایاکہ مسیحیوں کی تاریخیں اس بیا ن کی مخالفت کریں گی جیسے کہ ان کے ہاں ۳۳۷ ءکی مدت لکھی ہے.لیکن ان کی بات کااعتبار نہ کرنا اللہ جانتاہے کہ ان کی غلطی ہے.چنانچہ بعدکی
Page 515
تحقیق نے ان کی غلطی ثابت بھی کردی.اگرکہا جائے کہ اس جگہ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا آیاہے اس سے توپتہ لگتاہے کہ پہلی بات غلط تھی اس کاجوا ب یہ ہے کہ اگرپہلاقو ل لوگوں کاہوتاتوا س فقرہ سے اس کی تردید نکلتی.لیکن پہلی آیت میں چونکہ کفار کاقول نقل نہیں کیا بلکہ بغیر ان کے حوالہ کے زمانہ بتایا ہے اس لئے اس جملہ سے تردید نہیں نکلے گی بلکہ تاکید نکلے گی اورمطلب یہ ہوگا کہ اس زمانہ کے بارہ میں لوگ اختلاف کریںگے مگروہ غلطی پر ہوں گے صحیح زمانہ یہی ہے.اَبْصِرْ بِهٖ وَ اَسْمِعْ.وہ خو ب دیکھنے والا اورسننے والا ہے.یعنی اللہ تعالیٰ کابیان درست ہے دوسروں کانہیں.نیزان الفاظ سے اس طرف اشار ہ کیا ہے کہ انسانوں کے حالات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتاہے جب تک انسان شرک سے پاک رہیں وہ ان کی مددکرتاہے جب شرک میں مبتلاہوجائیںاللہ تعالیٰ کی نصرت جاتی رہتی ہے.وَ اتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ١ؕۚ لَا مُبَدِّلَ اورتیرے رب کی کتاب میں سے جو(حصہ)تجھ پروحی (کے ذریعہ سے نازل)ہوتاہے اسے پڑھ(کرلوگوں لِكَلِمٰتِهٖ١۫ۚ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا۰۰۲۸ کو سنا )اس کی باتوں کو کوئی بھی تبدیل کرسکنے والانہیں ہے اوراسے چھو ڑکر توکوئی پناہ کی جگہ نہیں پائےگا.حل لغات.اُتْلُ اُتْلُ تَلَایَتْلُوْسے امر کاصیغہ ہے اورتَلَاالْکَلَامَ تِلَاوَۃً کے معنے ہیں قَرَأَہٗ.اس کو پڑھا (اقرب)پس اُتْلُ کے معنے ہیں پڑھ.المُلْتَحَدُ اَلمُلْتَحَدُ: اَلْمَلْجَأُ.پنا ہ گاہ (اقرب) تفسیر.اصحاب کہف کا واقعہ بطور پیشگوئی ہے اس آیت میں یہ مضمون آکر کھو ل دیاکہ اس واقعہ کوہم بطورقصہ نہیں بیا ن کررہے بلکہ اسی طرح تیری امت کے ساتھ بھی ہونےوالا ہے.اوریہ بھی کہ جومضمون اوپر بیان ہواہے اس کے بعض حصے پیشگوئی کے طورپر ہیںاوربعض اخبار صادقہ ہیں.اس مضمون کااشارہ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ کے الفاظ سے نکلتاہے.اگریہ پیشگوئی نہ ہوتی تویہ کیوں فرماتاکہ خدا کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا.سابق کے واقعات کے بدلنے یانہ بدلنے کاتوکوئی سوال ہی نہیں ہوتا.پس اس آیت نے میری اوپرکی تفسیر کی تصدیق کردی ہے اوراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنہوں نے اوپرکی آیات کو صرف ماضی کاایک واقعہ سمجھا ہے انہوں نے غلطی
Page 516
کی ہے.ا ن میں کچھ سابق کے واقعات ہیں اور کچھ اصحاب کہف کے قائم مقاموں اوران کی آئندہ نسل کے متعلق پیشگوئیا ں ہیں.ایک اوررنگ میں بھی یہ آیات پیشگوئیوں پر مشتمل ہیں.اورو ہ اس طرح کہ جیساکہ میں بتاچکا ہوں اس قصہ کے بتانے میں یہ بھی حکمت ہے کہ ایسے ہی واقعات مسلمانوں کے ایک حصہ کو بھی پیش آنے والے ہیں.یعنی ان کوبھی اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان لانے کی وجہ سے تکالیف دی جانے والی ہیں.چنانچہ اس کی تصدیق حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں قَالَ رَسُو لُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَصْحَابُ الْکَھْفِ اَعْوَانُ الْمَھْدِیِّ (درمنثور زیر آیت الکہف ۹.۱۲بحوالہ ابن مردویہ)یعنی اصحاب کہف مہد ی کے مرید اوراس پر ایما ن لانے والے لوگ ہیں.اب ا س کے یہ معنے نہیں کہ پہلے کوئی اصحاب کہف نہیں گذرے.کیونکہ خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب کہف کی ہڈیاں تک دیکھی ہیں (جیسا کہ اوپر روایت گذر چکی ہے )بلکہ اس کے صرف یہ معنے ہیں کہ اصحاب کہف کاسامعاملہ مہد ی پرایمان لانے والوں سے بھی گذرے گااوران کو بھی خداکے کلام پر ایمان لانے کی وجہ سے تکالیف دی جائیں گی.وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ اوراپنے آپ کوان لوگوں کے ساتھ رکھ جو اپنے رب کو اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے صبح و شام الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ١ۚ تُرِيْدُ پکارتے ہیں اورورلی زندگی کی زینت چاہتے ہوئے تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں.زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا١ۚ وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ اورجس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کردیاہو اوراس نے اپنی گری ہوئی خواہش کی پیروی اختیارکی ہو ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا۰۰۲۹ اوراس کامعاملہ حد سے بڑھا ہواہواس کی فرمانبرداری مت کر.حل لغات.اِصْبِرْ وَاصْبِرْ صَبَرَ سے امر کاصیغہ ہے.اورصَبَرَ نَفْسَہُ عَلَی کَذَاکے معنے ہیں
Page 517
حَبَسَھَا.نفس کو کسی بات پر روکے رکھا (اقرب) مزید تشریح کے لئے دیکھو رعد۲۳ صَبْرٌ کے معنے ہیں تَرْکُ الشِّکْوٰی مِنْ اَلَمِ الْبَلْوٰی لِغَیْرِاللہِ لَا اِلَی اللہِ کہ مصیبت کے دکھ کا شکویٰ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہ کرنا.فَاِذَا دَعَا اللہَ الْعَبْدُ فِیْ کَشْفِ الضُّرِّ عَنْہُ لَا یُقْدَحُ فِیْ صَبْرِہٖ.اگر بندہ اپنی رفع مصیبت کے لئے خدا تعالیٰ کے پاس فریاد کرے تو اس کے صبر پر اعتراض نہ کیا جائے گا.وَقَالَ فِی الْکُلِّیَّاتِ اَلصَّبْرُ فِی الْمُصِیْبَۃِ.اور کلیات میں لکھا ہے کہ صبر مصیبت کے وقت ہوتا ہے.وَصَبَرَ الرَّجُلُ عَلَی الْاَمْرِ نَقِیْضُ جَزِعَ اَیْ جَرُؤَ وَشَجُعَ وَتَجَلَّدَ اور صبر جزع یعنی شکویٰ کرنے اور گھبرانے کے مقابل کا لفظ ہے اور صبر کے معنے ہوتے ہیں دلیری دکھائی.جرأت دکھائی.ہمت دکھائی.اور صَبَرَ عَنِ الشَّیْءِ کے معنے ہیں اَمْسَکَ عَنْہُ کسی چیز سے رکا رہا.اَلدَّابَۃَ حَبَسَہَا بِلَاعَلَفٍ.اور صبر کا مفعول دابۃ ہو تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ جانور کو بغیر چارہ دینے کے روکے رکھا.صَبَرْتُ نَفْسِیْ عَلٰی کَذَا کے معنے ہیں میں نے اپنے نفس کو کسی چیز پر قائم رکھا یا کسی چیز سے روکے رکھا.چنانچہ انہی معنوں میں صَبَرْتُ عَلَی مَااَکْرَہٗ وَصَبَرْتُ عَمَّا اُحِبُّ کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ تکلیف دہ حالت پر میں نے نفس کو استقلال سے قائم رکھا اور پسندیدہ امور سے نفس کو باز رکھا.گویا صبر کے تین معنے ہوئے گناہ سے بچنا اور اپنے نفس کو اس سے روکے رکھنا.(۲)نیک اعمال پر استقلال سے قائم رہنا.(۳)جزع فزع سے بچنا.(اقرب) الغَدٰوۃ اَلْغَدَاۃُ کے معنے صبح.صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت.اس کی جمع غُدُوٌّہے.مزید تشریح کے لئے دیکھو رعدآیت نمبر ۱۶ اَلْغَدَاۃُ :اَلْبُکْرَۃُ صبح اَوْمَابَیْنَ صَلٰوۃِ الْفَجْرِ وَطُلُوْعِ الشَّمْسِ صبح کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت اس کی جمع غدو ہے.(اقرب) العشيّ.اَلْعَشِیُّ: اٰخِرُ النَّھَارِ وَقِیْلَ مِنْ صَلوٰۃِ الْمَغْرِبِ اِلی الْعَتَمَۃُ.دن کے آخری حصہ کو عشی کہتے ہیں بعض کے نزدیک مغرب سے عشاتک کا وقت عشیّ کا ہے(اقرب) الوجہُ.اَلْوَجْہُ :نَفْسُ الشَّیْءِ.خود وہی چیز.اَلْوَجْہُ مِنَ الدَّھْرِ:اَوَّلُہٗ.زمانہ کی ابتداء.سَیِّدُ الْقَوْمِ.قوم کاسردار.اَلْجَاہُ.عزت.اَلْـجِھَۃُ.طرف.مَایَتَوَجَّہُ اِلَیْہِ الْاِنْسَانُ مِنْ عَمَلٍ وَغَیْرِہ.مطمح نظر.الْقَصْدُ وَالنِّیَّۃُ.قصداور ارادہ.اَلْمَرْضَاۃُ.رضامندی (اقرب)
Page 518
لَاتَعْدُ:لَاتَعْدُ عَدَا(یَعْدُ وْعَدْوًا)سے نہی مخاطب کاصیغہ ہے اورعَدَی فُلَانًا عَنِ الْاَمْرِ کے معنے ہیں صَـرَفَہٗ وَشَغَلَہٗ.اس کو کسی کام سے ہٹایا اورروکے رکھا.عَدَاالْاَمْرَ وَعَنِ الْاَمْرِ جَاوَزَہٗ وَتَرَکَہٗ.کسی کام کوترک کردیا اورچھو ڑ دیا.(اقرب) اَغْفَلْنَا اَغْفَلْنَااَغْفَلَ سے جمع متکلم کا صیغہ ہے اوراَغْفَلَ الشَّیْءُ بِمَعْنٰی غَفَلَ عَنْہُ(تَرَکَہُ وَسَھَا عَنْہُ)کسی چیز کو ترک کردیا.اوراسے بھو ل گیا.(اقرب) اَلْھَویٰ.اَلْھَوٰی اِرَادَ ۃُالنَّفْسِ.نفس کااراد ہ خواہش.اَلْعِشْقُ یَکُوْ نُ فِی الْخَیْرِ وَالشَّرِِّّ.کسی عمدہ یابری چیز کی خواہش کی شدت.اَلْمَھْوِیُّ مَحْمُوْدًا کَانَ اَوْمَذْمُوْمًاثُمَّ غَلَبَ عَلٰی غَیْرِ الْمَحْمُوْدِ.جس سے محبت کی جائے خواہ وہ محبوب پسندید ہ ہو یا ناپسندیدہ.لیکن آہستہ آہستہ اس کااستعمال بر ے معنوں میں ہونے لگ گیا ہے.اورجب فُلَانٌ اتَّبَعَ ھَوَاہُ کامحاور ہ بولتے ہیں تواس کےمعنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگارہا.اوریہ بول کر مذمت مقصود ہوتی ہے.(اقرب) فُرُطًا اَلْفُرُطُ:اَلظُّلْمُ وَالْاِعْتِدَاءُ.ظلم اورزیادتی.اَلْاَمْرُ الْمُجَاوَزُفِیْہِ عَنِ الْحَدِّ.حداور انتہاء سے بڑھا ہوا اَلْاَمْرُالْمَتْرُوْکُ.چھوڑاہواکام.جیسے کہتے ہیں.كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا.وَقِیْلَ اِسْرَافًا وَ تَضْیِیْعًا.اور بعض نے فرط کے معنے اسراف او رتضییع کے کئے ہیں(اقرب) تفسیر.اس آیت کا مخاطب ہر پڑھنے والا ہے نہ کہ آنحضرت صلعم اس آیت نے اوپر کے معنوں کو اورواضح کردیاہے.اس آیت کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں.بلکہ قرآن کریم کے پڑھنے والے وہ شخص ہیں جن کواس زمانہ کے دیکھنے کاموقعہ ملے.ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نمازیں پڑھایا کرتے تھے.ان کو کس طرح کہا جاسکتاتھاکہ جو صبح و شام نمازیں پڑھ رہے ہیں توان کے ساتھ رہ.اصل میں یہاں یہ بتایا ہے کہ مسیحی اقوام کی ترقی کے وقت ایک ایسی جماعت ہوگی جو اسلام پر قائم ہوگی اوران کے ساتھ لوگوںکوملنے کاحکم دیاگیاہے.اس آیت کے مخاطب یقیناً وہ مسلمان ہیں جواس زمانہ میں اسلام کی ترقی کو سیاسی اسباب کے ساتھ وابستہ قرار دیتے ہوں گے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس غلطی میں مبتلانہ ہونا بلکہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوجانا جوصبح شام نمازوں میں دعائیں کررہے ہوں گے اوراللہ تعالیٰ کے فضل کو دعائوں کے ذریعہ سے بلارہے ہوں گے.پھر فرماتا ہے اس نمازی جماعت سے اپنی نظر یں ہٹاکراو ر طرف نہ لے جانا کیونکہ گودنیا کی زینت اوراس کی ترقی کے سامان ان سے باہر ملیں گے لیکن اس میں خدا تعالیٰ کی رضاتوحاصل نہ ہوگی.پس دنیاوی
Page 519
لالچوں کی وجہ سے اس بظاہر حقیر نظرآنے والی جماعت کوحقیر مت جاننا اوران لوگوں کی پیروی نہ کرنا جوذکر الٰہی اورتبلیغ سے غافل ہوںگے اورڈنڈے کے زورسے ان قوموں کو سیدھاکرناچاہیں گے اورافراط و تفریط کی مرض اور سیاسیات کی ہواوہوس میں مبتلاہوں گے.اس آیت میں اس طر ف بھی توجہ دلائی ہے کہ اس زمانہ میں تین باتیں مسلمانوں کے مصائب کاموجب ہوں گی.ایک تو لوگ عبادت سے غافل ہوجائیں گے عبادت کی طرف توجہ نہ رہے گی.دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں دنیا کے اموال کی محبت بڑھ جائے گی تیسری بات یہ ہےکہ عیش وعشرت کابڑازور ہوگا.ایسے وقت میں مومن کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ عبادت میں مشغول رہے اورمال کی طرف رغبت نہ کرے اوراپنی جائزضروریات پوری کرکے باقی حصہ مال کا دین کی اشاعت میں خرچ کرے.وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ١۫ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ اور(لوگوںکو)کہہ دے(کہ)یہ سچائی تیرے ر ب کی طرف سے ہی (نازل ہوئی)ہے پس جوچاہے (اس پر ) فَلْيَكْفُرْ١ۙ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا١ۙ اَحَاطَ بِهِمْ ایمان لائے اورجوچاہے (اس کا )انکار کرد ے (مگریہ یاد رکھے کہ )ہم نے ظالموںکے لئے یقیناً ایک آگ تیار سُرَادِقُهَا١ؕ وَ اِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا۠ يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ کی ہے جس کی چار دیوار ی نے (اب بھی)انہیں گھیراہواہے.اوراگر وہ فریاد کریں گے توایسے پانی سے ان کی يَشْوِي الْوُجُوْهَ١ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ١ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا۰۰۳۰ فریادرسی کی جائے گی جوپگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا (اور)چہروں کوجھلس دےگا.و ہ بہت بُری پینے کی چیز ہوگی.اوروہ (یعنی آگ)بُراٹھکانا ہے.حل لغات.سُـرَادِقٌ سُـرَادِقٌکے معنے ہیں (۱)وہ سائبان جوصحن پر لگایا جاتا ہے(۲)پردہ یاقنات یاخیمہ کے چاروں طرف کا پردہ (۳)کپڑے کاخیمہ (۴)غبار(۵)دھوئیں کابگولہ (اقرب)
Page 520
اَلْمُھْلُ.اَلْمُھْلُ مہل سب معدنیات کو کہتے ہیں مثلاً چاندی لوہے وغیر ہ کو.(۲)پتلا تیل.سیّال چیز جس میں جل اٹھنے کامادہ ہوتاہے.(۳)زہر(۴)پیپ(۵)خصوصاً مردہ کی پیپ(۶)پگھلاہواتانبا (۷)تیل (۸)تلچھٹ یعنی تیل کی میل جواس کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے (اقرب) یَشْوِیْ.یَشْوِیْ شَوٰی سے مضارع ہے اورشَوَی اللَّحْمَ کے معنی ہیں جَعَلَہٗ شِوَاءً گوشت کو بھُونا.اَلْمَاءَ: اَسْخَنَہُ.پانی کوگرم کیا (اقرب) مُرْتَفَقًا.اِرْتَفَقَ الرَّجُلُ:طَلَبَ رَفِیْقًا.اس نے کسی ساتھی کی تلاش کی.اِسْتَعَانَ.مدد مانگی.اِتَّکَأَ عَلٰی مِرْفَقٍ وَقِیْلَ عَلٰی اَلْمِخَدَّۃِ.کہنی یاتکیہ پر ٹیک لگائی.اِرْتَفَقَ الْاِنَا ءُ: اِمْتَلَأَ.برتن(پانی وغیر ہ سے ) بھر گیا.اِرْتَفَقَ الْقَوْمُ:تَرَافَقُوْافِی سَفَرٍ.لوگ سفر میں ایک دوسرے کے رفیق بنے.اَلْمُرْتَفَقُ اِرْتَفَقَ سے اسم مفعول ہے اس کے معنے ہیںاَلْمُتَّکَأُ.تکیہ او رسہارالگانے کی چیز (اقرب) تفسیر.وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ.توکہہ دے کہ یہ بات جو میں نے بتائی ہے یعنی مسلمانوں کی ترقی اوران قوموں کی تباہی.یہ ہوکر رہے گی.اس سے صاف پتہ لگتاہے کہ یہ پیشگوئی ہے.فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ الآیۃ یعنی دین کے معاملہ میں زبردستی توہے نہیں.جوشخص جس بات کو چاہے اختیار کرے وہ اپنے عمل کا نتیجہ بھگتے گامگراسے جبراً نہیں منوایاجائے گا.اس میں اس طر ف اشارہ ہے کہ وہ جہاد کا زمانہ نہ ہوگا.بلکہ تبلیغ کا زمانہ ہو گا.لوگوں کے سامنے صداقت رکھنا مسلمانوں کافرض ہوگاآگے کوئی مانے یانہ مانے.کسی سے جنگ کرنی جائزنہ ہو گی.یورپین اقوام کی تباہی جنگ کے ذریعہ مقدر ہے چونکہ یہ سوال ہوسکتاتھا کہ اگر جنگ اورجہاد نہ ہوگا تو مسلمانوں کی کمزورحالت کس طرح بدلے گی.ا س کا جواب یہ دیا کہ ہم اس کے سامان خود پیداکریں گے اور یوروپین اقوام کوجنگ کا عذاب گھیر لے گا.اورگویا جنگ ان کے گھروں کے گرد خیمے لگالے گی.اورجس قد روہ امن کے لئے کوشش کریں گے اورامن امن کہہ کر چلّائیں گے.اسی قدر پگھلتاہوالوہا اورتانبہ ان کے مونہوں پر ڈالاجائے گا.یعنی امن کی پکار توہو گی لیکن نتیجہ توپوں کے گولے اوربم ہی نکلے گا.اوران کے ملک رہائش کے قابل نہ رہیں گے.بلکہ براٹھکانہ بن جائیںگے.اِرْتَفَقَ کے معنے تعاون اوررفاقت کے بھی ہوتے ہیں ان معنوں کے روسے معنے یہ ہوں گے کہ قومیں امن کی خاطر دوسری قوموں سے دوستیاں کریں گی.لیکن ان دوستیوں کانتیجہ جنگ ہی نکلے گانہ کہ صلح.
Page 521
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ (ہاں)یقیناً جولو گ ایما ن لائے ہیں او رانہوں نے نیک (اورمناسب حال )عمل کئے ہیں(وہ بڑے اجر اَحْسَنَ عَمَلًاۚ۰۰۳۱ پائیں گے )جنہوں نے اچھے کام کئے ہوں ہم ان کااجر ہرگز ضائع نہیں کیا کرتے.تفسیر.یعنی اس کے مقابل پر جولوگ خداکے کلام پر ایما ن لائیں گے اورا س ایما ن کے مطابق عمل کریں گے ان کے اجر ضائع نہ ہوںگے یعنی باوجود اس کے وہ ظاہر شان وشوکت سے محروم ہوں گے پھر بھی ان کے اعمال آہستہ آہستہ دنیا میں امن کی صورت پیداکرتے چلے جائیں گے.اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ ان لوگوںکے لئے دائمی رہائش کے باغات (مقدر)ہیں (ان میں )ان کے (اپنے انتظام کے )نیچے نہریں بہتی يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُوْنَ ثِيَابًا ہوںگی ان کے لئے ان میں سونے کے کنگنوں کی قسم کے زیوربنوائے جائیں گے اوروہ باریک ریشم کے اورموٹے خُضْرًا مِّنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى ریشم کے سبزکپڑے پہنیں گے.ان (بہشتوں )میں آراستہ پلنگوں پر تکئے لگائے (ہوئے بیٹھے )ہوں گے.یہ کیا الْاَرَآىِٕكِ١ؕ نِعْمَ الثَّوَابُ١ؕ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًاؒ۰۰۳۲ ہی اچھا اجر ہے اوروہ بہت ہی اچھا ٹھکانا ہے.حلّ لُغَات.یُحَلَّوْنَ حَلَّی سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ یَحُلُّوْنَ ہے اوریُحَلَّوْنَ ا س سے مجہول کاصیغہ ہے.اورحَلَّی الْمرْأَ ۃَ تَحْلِیَۃً کے معنے ہیں اَلْبَسَھَا حُلْیًا.عورت کو زیور پہنائے (اقرب)
Page 522
ثیابًا:ثِیَابًا ثَوْبٌ کی جمع ہے اورثَوْبٌ کے معنے ہیں.اَللِّبَاسُ مِنْ کِتَّانٍ وَقُطُنٍ وَصُوْفٍ خَزٍّوَ فِرَاءٍ.روئی.اون.ریشم.پوستین وغیرہ کے کپڑے (اقرب) سُندُس سُنْدُسٌ کے معنے ہیں نہایت باریک اور نفیس ریشمی کپڑا یادیبائے نازک.اورکلیا ت میں اس کے معنی ریشمی گدیلے اوربسترو ں کے کئے ہیں (اقرب) اِستبرق اِسْتَبْرَقٌ:اَلدِّیْبَاجُ الْغَلِیْظُ.موٹاریشم.اسے معرّب یعنی غیر عربی زبان کاقرار دیاگیا ہے.(اقرب) اَلْاَرَائِکُ.اَلْاَرَائِکُ اَرِیْکَۃٌ کی جمع ہے اوراَرِیْکَۃٌ کے معنے ہیں.سَرِیْرٌ مُنَجَّدٌ مُزَیَّنٌ فِی قُبَّۃٍ اَوْبَیْتٍ.ایسا مزین تخت جوکسی قبّہ یاخیمہ میں لگایا گیاہو (اقرب) تفسیر.سونے کے کڑے اور ریشمی کپڑے پہننے سے مراد سونے کے کڑوں پراعتراض ہوتاہے کہ مردوں کے لئے سونے کے کڑے پہننے ناجائز ہیں.ا س کا جواب یہ ہے کہ اگر تواس سے مرا د دنیاہو تواس سے مراد یہ لی جائے گی کہ ان کو بادشاہتیں ملیں گی.سونے کے کنگن پہننے سے مراد بادشاہت ہے.پرانے زمانہ میں سونے کے کنگن بادشاہ پہنا کرتے تھے.پس یہاں بتایا ہے کہ مسلمانوں کوبادشاہ بنایاجائے گااوراگر اس سے مراد اگلاجہان ہوتواس جہاں کی ہرشے روحانی ہے.وہاںسونے کے کڑوں سے مادی سونے کے کڑے مراد نہیں ہوسکتے.بلکہ خاص قسم کے اعزازمراد لئے جائیں گے.مِنْ سُنْدُسٍ وَّ اِسْتَبْرَقٍیعنی جیسے ریشمی کپڑا پہننے سے آرام اورلذت محسوس ہوتی ہے.اسی طرح وہاں بھی ایسالباس ملے گاجس سے لذت اورآرام محسوس ہوگااوراس کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں.کہ یہ چیز یں جن کے لائق ہوں گی ان کو پہنائی جائیں گی.جیسے حضرت عمرؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی کپڑادیاتوانہوں نے کہا یارسول اللہ مجھے آپ نے یہ کیسے دیا.مردوں کے لئے توریشم پہننا ناجائز ہے اس پر آنحضرت صلعم نے فرمایا تم اسے اپنی بیوی کو پہناسکتے ہو (مسلم کتاب اللباس والزینۃ باب تحریم لبس الحریر و غیر ذالک للرجال).نِعْمَ الثَّوَابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.یعنی قرآن کریم پر سچاایمان لانے والوں کو جوانعامات ملیں گے وہ تباہی کی طرف نہ لے جائیں گے بلکہ ان کے نتیجہ میں امن اوراطمینان پیدا ہوگا اورحَسُنَتْ مُرْتَفَقًاسے یہ بتایا کہ قرآنی تعلیم پر چل کر جودوستیاں اوررفاقتیں ہوں گی و ہ چونکہ اخلاص پر مبنی ہوں گی اورذاتی اغراض ان کے پیچھے پوشیدہ نہ ہوںگی.ان دوستیوں کے نتیجہ میں لڑائیاں نہیں ہو ں گی بلکہ امن حاصل ہوگا.
Page 523
وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ اورتوان کے سامنے ان دوشخصوںکی حالت بیان کر جن میں سے ایک کوہم نے انگوروں کے دوباغ دیئے تھے مِنْ اَعْنَابٍ وَّ حَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَّ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًاؕ۰۰۳۳ اورانہیں ہم نے کھجوروں کے درختوں سے (ہرطر ف سے)گھیر رکھاتھا.اورہم نے ان کے درمیا ن کچھ کھیتی( بھی) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا١ۙ وَّ پیداکی تھی ان دونوں باغوں نے اپنا (اپنا )پھل (خوب )دیا.اوراس میں سے کچھ(بھی)کم نہ کیا.اوران فَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًاۙ۰۰۳۴ کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کی (ہوئی )تھی.حلّ لُغَات.وَاضْرِبْ لَھُمْ مَثَلًا کے معنی ہیں ان کے سامنے مثال بیان کر مزید تشریح کے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر۲۵.اَلْمَثَلُ کے معنے ہیں اَلشِّبْہُ وَالنَّظِیْرُ.مشابہ.اَلصِّفَۃُ بیان.اَلْحُجَّۃُ.دلیل.یُقَالُ اَقَامَ لَہُ مَثَلًا اَیْ حُـجَّۃً.اَقَامَ لَہٗ مَثَلًا کہہ کر مثل سے مراد دلیل لیتے ہیں.اَلْحَدِیْثُ عام بات.اَلْقَوْلُ السَّائِرُ ضرب المثل اَلْعِبْرَۃُ عبرت.اَلْاٰیَۃُ.نشان.(اقرب) اور ضَرَبَ لَہُ مَثَلًا کے معنے ہیں وصَفَہُ وَقَالَہٗ وَبَیَّنَہٗ مثل کو بیان کیا.ا ور اچھی طرح سے واضح کیا.جَنَّتَین جَنَّتَیْنِ جَنَّۃٌ کاتثنیہ ہے مزید تشریح کے لئے دیکھو رعد آیت نمبر۲۴.اَلْجَنَّۃُ جَنَّ میں سے ہے.وَاَصْلُ الْجَنِّ سَتْرُ الشَّیْءِ.جَنَّ کے اصل معنے کسی چیز کو ڈھانپنے کے ہیں.یُقَالُ جَنَّہٗ اللّیْلُ چنانچہ جَنَّہُ اللَّیْلُ کا محاورہ انہی معنوں میں مستعمل ہے کہ رات نے اس کو ڈھانپ لیا.وَالْجَنَّۃُ: کُلُّ بُسْتَانٍ ذِیْ شَجَرٍ یَسْترُ بِاَشْجَارِہِ الْاَرْضَ.اور جنت ہر اس باغ کو کہتے ہیں جس میں کثرت سے درخت ہوں اور وہ درختوں کے جھنڈ سے زمین کو ڈھانپ لے.وَقَدْ تُسَمَّی الْاَشْجَارُ السَّاتِرَۃُ جَنَّۃٌ اور ڈھانپنے اور چھپانے والے یعنی گھنے درختوں کو بھی جَنَّۃٌ کہتے ہیں.وَسُمِّیَتِ الْجَنَّۃُ إِمَّا تَشْبِیْہًا بِالْجَنَّۃِ فِی الْاَرْضِ وَاِنْ
Page 524
کَانَ بَیْنَہُمَا بَوْنٌ.وَاِمَّا لِسَتْرِہِ نِعَمَہَا عَنَّا الْمُشَارَ اِلَیْہِ بِقَوْلِہِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَااُخْفِیَ لَہُمْ مِنْ قُرَّۃِ اَعْیُنٍ.اور جنت کو اس لئے جنت کے نام سے پکارا گیا ہے کہ یا تو وہ دنیاوی باغات کے مشابہ ہے اگرچہ ان میں اور اس میں بہت فرق ہے.یا اس وجہ سے کہ اس کی نعمتیں ہم سے پوشیدہ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ میں فرمایا ہے کہ جنت کی نعماء کا کسی کو علم نہیں.(مفردات) حَفَفْنٰھُمَا.حَفَفْنَا حَفَّ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے اورحَفَّہُ الْقَوْمُ وَبِہِ وَحَوَاِلیْہِ کے معنی ہیں اَحْدَقُوْابِہِ وَ اَطَافُوْ اَوِاسْتَدَارُوْا لوگوں نے اسے ہر طرف سے گھیرلیا اوراس کے اردگردحلقہ بنالیا (اقرب) پس حَفَفْنٰھُمَا کے معنی ہوں گے کہ ان دونوں کو ہم نے گھیر رکھاتھا.وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْہُ شَيْـًٔا.تَظْلِمُ ظَلَمَ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے.اورظَلَمَ فُلَانًا حَقَّہ کے معنے ہیں نَقَّصَہُ اِیَّاہُ اسے اس کے حق سے کم دیا.اورلَمْ تَظْلِمْ مِنْہُ شَيْـًٔا کے معنی ہیں.لَمْ تَنْقُصْ.کہ اس نے کچھ بھی کم نہ دیا(اقرب) تفسیر.بعض نے کہاہے کہ اس آیت میں کسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے.لیکن اکثرمفسرین کاخیال ہے کہ یہ ایک مثال ہے.جنہوں نے اس کوواقعہ کہاہے ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ دوآدمی یہود میں سے تھے.اور بعض نے کہاہے کہ عرب میں سے تھے (القرطبی و فتح البیان زیر آیت ھذا).لیکن دو باغ کی حیثیت والا کوئی آدمی اس رتبہ کانہیں سمجھاجاسکتا.جس کا ذکر تاریخ میں کیاجائے.یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یاتویہ تسلیم کیاجائے کہ اس قسم کے فخریہ کلمات دنیا میں اور کوئی شخص نہیں کہتا.بس اسی شخص نے کہے تھے.اوریایہ تسلیم کیاجائے.کہ اس زمانہ میں دنیا بھر میں کوئی درخت نہ تھے بس ایک اس شخص کے دوباغ تھے.اس لئے اس کے واقعہ کوتاریخ میں محفوظ رکھا گیا.اس مثال کی تفصیل سے معلو م ہوتاہے کہ اس سے ہمیں کچھ سمجھانامقصود ہے.ورنہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی.میراخیال ہے کہ الہامی کتابوں میں جب کوئی ایسی مثال ہو جوادبی نہ ہو بلکہ اس میں کسی باریک مضمون کی طرف اشارہ ہو تواس کی حقیقت معلوم کرنے کابہترین ذریعہ یہی ہے.کہ اپنی عقل سے کام لینے کی بجائے ہم تعبیر رویا کے علم سے مدد لیں کیونکہ خواب بھی ایک تمثیلی زبان ہے اورضروری ہے کہ دونوں قسم کی تمثیلیں جن کامنبع ایک ہے آپس میں مشابہت رکھتی ہوں.
Page 525
باغ کی تمثیل کی تشریح باغ کی تشریح ہم دنیاوی لحاظ سے مال و دولت سے کرسکتے ہیں.اوردرختوں سے یہ مراد لے سکتے ہیں کہ وہ کھیت کی حفاظت کرتے تھے.کیونکہ زمینداروں کے کھیت کی حد بندی درختوں سے اچھی طرح ہوسکتی ہے.بے شک یہ بھی ایک تعبیر ہے.جوہم اپنے ذہن سے کرسکتے ہیں.لیکن ہم کیوں نہ علم تعبیر سے مدد لیں.اورپھر قرآن کریم کو دیکھیں.کہ کیا و ہ ان معنوں کی تصدیق کرتا ہے یانہیں.علم تعبیرالرویا میں باغ دیکھنے کے متعلق لکھاہے.وَرُبَّمَا دَلَّ الْبُسْتَانُ عَلَی الزَّوْجَۃِ وَالْوَلَدِ وَالْمَالِ وَطِیْبِ الْعَیْشِ وَزَوَالِ الْھُمُوْمِ.....عَلَی دَارِ السُّلْطَانِ الْجَامِعَۃِ لِلْجُیُوْشِ وَالْجُنُوْدِ (تعطیر الانا م زیر لفظ بستان) یعنے اگر کوئی خواب میں باغ دیکھے تواس سے مراد بعض دفعہ بیوی ،اولاد ،مال،زندگی کے اچھے سامان غموں کادور ہوناہوتاہے اوربعض دفعہ شاہی محل مراد ہوتاہے جس میں فوج اورلشکر جمع ہوتے ہیں.یعنی چھائونیاں یا ہیڈکوارٹرز.اورانگور خواب میں دیکھنا رزق حسن پر دلالت کرتاہے اورایسے دائم ووسیع رزق پر جس کاذخیرہ رکھا جائے.اوراس نفع پر جوعورتو ں کے ذریعے پہونچے (تعطیر الانا م زیر لفظ عنب ) کھجور کی تعبیر کھجور کے متعلق لکھا ہے کہ مَنْ مَلِکَ نَخْلًا کَثِیْرًا فَاِنَّہُ یَتَوَلَّی عَلٰی رِجَالٍ بَقَدْرِذَالِکَ وَاِنْ کَانَ تَاجِرًا اِزْدَادَتْ تِـجَارَتُہٗ(تعطیر الانا م زیر لفظ نخل )یعنی جو خوا ب میں دیکھے کہ وہ کھجور کامالک ہواتواسی تعداد میں آدمیوں پر وہ حکومت کرےگا.اوراگر و ہ تاجر ہوتواس کی تجارت میں زیادتی ہوگی.پھلوں کے متعلق لکھا ہے وَالثِّـمَارُ کَرَامَۃٌ جدیدۃٌ طریَّۃٌیعنی تازہ بتازہ عزت کے سامان ملنا.ومَنْ رَأَی اَنَّہٗ قَدْ زَرَعَ فِیْ اَرْضٍ فَھُوَ لِلسُّلْطَانِ سَعَۃٌ فِی مَمْلِکَتِہٖ...وَالزَّرْعُ یَدُلُّ عَلَی الْعَمَلِ یعنی جودیکھے کہ اس نے کسی زمین میں کھیتی کی ہے.تواگر وہ بادشاہ ہے تواس کی حکومت وسیع ہوگی.اورباقی لوگوں کے لئے کھیتی سے مرادعمل ہوتاہے (تعطیر الانا م زیر لفظ زرع ).نہر کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے مراد عالیشان انسان ہوتا ہے.(تعطیر الانا م زیر لفظ نہر )اسی طرح لکھا ہے کہ جوخواب میں دیکھے کہ اس کے گھر سے نہر نکلی ہے.اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ نیک تعلیم دےگا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے.تواب یہ معنی ہوں گے کہ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ ہم نے ان میں سے ایک کے لئے دوباغ بنائے تھے یعنی مال اوراولاد عطا کی تھی.اورمِنْ اَعْنَابٍ کے معنی دائم رہنے والے کے بھی ہیں.پس مراد یہ ہے کہ ان کے مال اوراولاد کی ترقی لمبی ہوگی.چنانچہ قرآن کریم اس کی تصدیق کرتاہے جیساکہ آگے فرمایا اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا.کہ میں مال اورتعداد میں تجھ سے زیادہ ہو ں.حالانکہ پہلی آیات میں تعداد کاکوئی ذکرہی نہ تھا وَحَفَفْنٰهُمَا
Page 526
بِنَخْلٍ پہلے بتایا جاچکا ہےکہ نخل سے مراد آقا کے غلام ہوتے ہیں.پس انگور کے باغ کااحاطہ نخل سے کرنے کے یہ معنی ہوں گے.کہ فوجی طاقت سے وہ اپنے مال اوراولاد اورملک کی حفاظت کرے گا.وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا.زرع کے معنی عمل کے ہوتے ہیں.پس دونوں باغوں کے درمیان عمل ہوگا کے یہ معنی ہوں گے کہ ادھر بھی بادشاہت ہوگی جس کی حفاظت فوجیں کررہی ہوں گی.اورادھر بھی بادشاہت ہو گی جس کی حفاظت فوجیں کررہی ہوں گی اوران دونوں کے درمیان زرع ہوگی.یعنی درمیان میں معمولی حیثیت کی جائدا دہوگی جو بے حفاظت ہوگی.وَكِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا.یعنی یہ دونوں باغ اپنے اپنے وقت پر پھل دیتے رہے.وَ لَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْـًٔا.اور کبھی انہوں نے اپنے پھل دینے میں کمی نہیں کی.یہ عبارت بھی بتارہی ہے کہ اس جگہ با غ تمثیلی ہیں معروف باغ مراد نہیں.کیونکہ یہ قانون قدر ت ہے کہ پھل کسی سال زیاد ہ آتا ہے.کسی سال کم آتاہے.دونوں باغوں کے لئے مفرد کی ضمیر لانے میں حکمت نیزاس آیت سے ایک اوربات بھی معلوم ہوتی ہے اوروہ یہ کہ گودوباغوں کا ذکر کیا ہے.لیکن باوجود ان کے ایک جہت سے دوہونے کے دوسری جہت سے و ہ ایک بھی تھے.کیونکہ ان باغوں کے لئے ضمیر مفرد کی استعما ل کی ہے.یعنی اٰتَتَاکی جگہ اٰتَتْ فرمایا ہے.اورلَمْ تَظْلِمَا کی جگہ لَمْ تَظْلِمْ کالفظ استعمال کیاہے.اوریہ دونوں واحد مونث کے صیغے ہیں.ظاہر ہے کہ اس فرق سے یہی مضمون پیداکرنامقصود ہے کہ بظاہردوباغ ہیں.لیکن اصل میں ایک ہی باغ ہے.یایوں کہو کہ ایک باغ کے دوحصے ہیں (اس میں کوئی شک نہیں کہ کِلْتَا کی طرف لفظاً ضمیر واحد مونث بھی پھرائی جاسکتی ہے.لیکن معناً ضمیر تثنیہ کی آنی چاہیے.علامہ بیضادی نے لکھا ہے.وَفِی الْحَاشِیَۃِ السَّعْدِیَۃِ فَاِنَّہُ اِسْمٌ مُفْرَدُاللَّفْظِ عِنْدَ الْبَصْرِیِّیْنَ وَمُثَنَّی الْمَعْنَی وَمُثَنَّی لَفْظًا وَمَعْنًی عِنْدَ الْبَغْدَادِیِّیْنِ (حاشیہ القونوی علی تفسیر البیضاوی جلد ۱۲ صفحہ ۷۹ زیر آیت ھذا)کہ حاشیہ سعدیہ میں ہے کہ بصریوں کے نزدیک کِلْتَا کالفظ بلحاظ معنی تثنیہ ہے.اوربلحاظ لفظ کے مفردہے مگربغدادیوں کے نزدیک کِلْتَا لفظاً اورمعناً دونوں طرح تثنیہ ہے.القونوی علی البیضاوی میں لکھاہے.کہ حریری نے درَّہ الغواص میں کہا ہے کہیَقُوْلُوْنَ کِلَا الرَّجُلَیْنِ خَرَجَا وَکِلْتَا الْمَرْأَتَیْنِ حَضَرَتَا.یعنی عرب کِلَا اورکِلْتَاکے بعد فعل تثنیہ لاتے ہیں.پس بغدادی ائمہ لغت کے مذہب کی بناء پر توقرآنی آیت میں اٰتَتَا آناضروری تھا.اورحریری کے قول کے
Page 527
مطابق بھی ا سی کوترجیح حاصل ہے صیغہ تثنیہ کالانا بہرحال جائز توہے.پس میرااستدلال یہ ہے کہ اول توتثنیہ کاصیغہ استعمال کرنا انسب تھا کم سے کم جائز تھا.اورلفظی طورپر انسب کو چھوڑ کردوسرے طریق کو اختیار کرنا قرآن کریم کے مسلمہ اصول کے مطابق ضرورکوئی معنوی حکمت رکھتا ہے.اوراس کی مثالیں کثر ت سے قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں.کہ وہ جائز اورصحیح الفاظ اورضمائر کے انتخاب میں بھی حکمتوں اورنئے مضمونوں کومدنظررکھتاہے.وَّ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ١ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ اوراسے بہت پھل حاصل( ہوتا)تھا.اسی وجہ سے اس نے اپنے ساتھی کو ا س سے باتیں کرتے ہوئے (فخریہ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا۰۰۳۵ طورپر)کہا(کہ دیکھ)تیری نسبت میرامال زیادہ اورجتھا معززہے.حلّ لُغَات.ثَمَرٌثَمَرٌکے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر ۳۸.الثَّمَرَاتُ- الثَّمَرَۃُ.حَمْلُ الشَّجَرِ.درخت کا پھل.اَلنَّسْلُ.نسل.اَلْوَلَدُ.لڑکا.ثَـمَرَۃُ الْقَلْبِ.اَلْمَوَدَّۃُ.دوستی.خُلُوْصُ الْعَھْدِ.خالص عہد.یُحَاوِرُہُ یُحَاوِرُہُ حَاوَرَ سے مضارع واحد مذکرغائب کاصیغہ ہے.اورحَاوَرَہُ (مُحَاوَرَۃً) کے معنی ہیں جَادَ بِہِ اس سے بات چیت کی.رَاجَعَہُ الْکَلَامَ اس کی بات کا جواب دیا (اقرب) اَعَزُّ اَعَزُّیہ عَزَّسے اسم تفضیل ہے اورعَزَّہُ(یَعُزُّ.عَزًا)کے معنی ہیں.قَوَّاہُ.اس کی طاقت بڑھائی.اسے تقویت دی.غَلَبَہٗ.اس پر غالب آگیا.اورعَزَّ(یَعِزُّ عِزًّا)کے معنی ہیں صَارَ عَزِیْزًا وہ معززہوگیا زبردست ہوگیا.قَوِیَ بَعْدَ ذِلَّۃٍ کمزور ہونے کے بعد طاقتور ہوگیا.ضَعُفَ.چونکہ یہ لفظ اضداد میں سے ہے.اس لئے اس کے معنی کمزورہوجانے کے بھی ہیں (اقرب) نفرًا:اَلنَّفَرُ:اَلنَّاسُ کُلُّھُمْ تمام لوگ مِنْ ثَلَاثَۃٍ اِلٰی عَشَرَۃٍ وَقِیْلَ اِلٰی سَبْعَۃٍ مِنَ الرِّجَالِ تین سے دس مردوں تک کاگرو ہ اوربعض کے نزدیک تین سے سات اشخاص تک کے گروہ کو نفر کہتے ہیں (اقرب) تفسیر.كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ.یعنی اس کی محنت کے بڑے بڑے نتیجے پیداہورہے تھے.اس حالت کو دیکھ کر
Page 528
اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میرامال تجھ سے زیادہ ہے.اورقوم کے لحاظ سے بھی تجھ سے زیادہ معززہوں.اب میں اس تمثیل کی حقیقت بیا ن کرتاہوں.سورۃ کے شروع میں بتایا گیاتھا.کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے مکہ والوں کوخدا کاپیغام پہونچایا.اوریہود کو پہنچانے والے ہیں.اسی طرح آپ مسیحیوں کوبھی بیدار کرنے والے ہیں اورپھر مسیحی قوم کی ابتدائی تاریخ بتائی کہ یہ قوم ان حالات میں شروع ہوئی تھی.کہ توحید کے لئے انہوں نے سخت سے سخت تکلیفیں اٹھائیں.مگربعد میں مشرک ہوگئی اوردنیا کے پیچھے پڑ گئی.اس تمثیل میں باغ سے مراد مسیحی قوم ہے اب اس تمثیل کے ذریعہ سے مسلمانوں اور مسیحیوں کے مقابلہ کا ذکر آتا ہے.اس تمثیل میں باغ والے سے مراد مسیحی قو م ہے.اورانگوروں کے باغ کی تمثیل اس لئے دی ہے کہ مسیحی قوم کوانگورکاباغ خود حضرت مسیح ناصر ی نے قراردیا ہے.اوراس با غ کی تمثیل ان آیات کی تمثیل سے ملتی ہے.حضرت مسیح کہتے ہیں ’’ایک شخص نے انگو رکاباغ لگایا.اوراس کے چاروں طرف گھیرااورکولہو کی جگہ کھودی.اورایک بُرج بنایا.اوراسے باغبانوں کے سپرد کرکے پردیس گیا.پھر موسم میں اس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا.تاکہ وہ باغبانوںسے انگور کے باغ کے پھل میں سے کچھ لے.انہوں نے اسے پکڑ کے مارا.اورخالی ہاتھ بھیجا.اس نے دوبارہ ایک اورنوکر کو ان کے پاس بھیجا انہوں نے اس پر پتھر پھینکے.اس کاسر پھوڑا.اوربے حرمت کرکے پھیربھیجا.پھراس نے ایک اورکوبھیجا.انہوں نے اسے قتل کیا.پھر اوربہتیروں کوان میں سے بعضوں کو پیٹا اور بعضوں کو مارڈالا.اب اس کاایک ہی بیٹاتھا جواس کوپیاراتھا.آخر کواس نے اسے بھی اس کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وے میرے بیٹے سے دبیں گے.لیکن ان باغبانوں نے آپس میں کہا یہ وارث ہے.آئوہم اسے مارڈالیں.تو میراث ہماری ہوجائے گی.اوانہوںنے اسے پکڑ کرقتل کیا.اورانگورکے باغ کے باہر پھینک دیا.پس باغ کامالک کیا کہے گا.وہ آوے گااور ان باغبانوں کو ہلاک کرکے انگوروں کاباغ اوروں کو دےگا.کیا تم نے یہ نوشتہ نہیں پڑھا.کہ وہ پتھر جسے معماروں نے ناپسند کیا وہی کونے کاسراہوا‘‘(مرقس باب ۱۲ آیت ۱تا۱۰) اس تمثیل میں حضرت مسیح نے مذاہب کو انگور کے باغ سے تشبیہ دی ہے.اورباغ کامالک خدا تعالیٰ کو بتایاہے.با غ کے متعلق وہی تشریح ہے جو قرآن کریم میں ہے.کہ بیچ میں انگوراورچاروں طرف باڑ.صر ف یہ فرق ہے کہ قرآن کریم نے باڑ کے درختوں کانام بھی بتایا ہے جس سے زائد معنی پیداکردیئے ہیں.غرض حضرت مسیح نے نبیوں کی مخاطب امتوں کو باغ بتایا ہے.اوران کی نگرانی کرنے والے علماء اوربادشاہوں کومالی.وہی معنی قرآن کریم میں ہیں.باغ سے مراد عیسائیت ہے اورانگور سے مراد مال اوردولت اوراولاد کی زیادتی ہے.اورکھجوروں سے مراد یہ
Page 529
ہے کہ مسیحیت اپنی ترقی کے زمانہ میں فوجوں پرانحصار رکھے گی.اوراپنی حفاظت کے زبردست سامان کرے گی.اورباغ کو ایک لحاظ سے دواورایک لحاظ سے ایک اس لئے قرار دیاہے.کہ سابق قوموں کے برخلاف مسیحیت کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی ترقی دوزمانوں میں ہوئی ہے.ایک اسلام سے پہلے اس کی ترقی کا زمانہ تھا.اوردوسرازمانہ اسلام کے تین سوسال بعد شروع ہوااورسات سوسال میں جاکر تکمیل کوپہونچا.یعنی سترھویںصدی میں ان ترقی کے دوزمانوں کے درمیان ان کی حالت زرع کی سی رہی.کہ وہ جانوروں کے پائو ںتلے روندے جانے اوراکھیڑے جانے کے خطرہ میں ہوتی ہے.اوران دونوں زمانوں کے درمیان جومسیحیت کے باغ کہلانے کے مستحق تھے.اللہ تعالیٰ نے ایک نہر چلادی تھی.یعنی اسلام کا زمانہ رکھ دیاتھا.جس نے مسیحی قوم کے دونوں باغوں کو ایک دوسرے سے جداکردیاتھا.ان دونوں زمانوں کے درمیان ایک عظیم الشان انسان پیداہوا.اوراللہ تعالیٰ نے امر معروف کاسلسلہ جاری کیا.پھر بتایا ہے کہ جب اسلام دنیا میں آگیا.تودونوں باغوں کے مالک نے یعنی عیسائی قوم کے لیڈروں نے مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کیا.کہ تمہاری کیاطاقت ہے.ہم کو توغیر معمولی طور پر دوزمانوں میں حکومت ملی ہے.خصوصاً و ہ زمانہ ترقی کا جو مسلمانوں کے زمانہ میں آیا.و ہ توبہت ہی شاندار ہوگا.اس پر انہیں خاص ناز ہوگا.کیونکہ اسی سے مسلمانوں کامقابلہ ہوگا.وَ دَخَلَ جَنَّتَهٗ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ١ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ اور(ایک دفعہ)وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا.(اوروہ اس طرح کہ )اس نے (اپنے تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًاۙ۰۰۳۶ ساتھی سے)کہا (کہ)میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہو.حل لغات.تَبِیْدُ تَبِیْدُ بَادَ سے مضارع واحد مؤنث غائب کاصیغہ ہے.اوربَادَ(یَبِیْدُ بُیُوْدًا) کے معنی ہیں ھَلَکَ کوئی چیز ہلاک ہوگئی.(اقرب)پس مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا کے معنی ہوں گے کہ میں خیال نہیں کرتا کہ وہ کبھی تباہ وہلاک ہو.تفسیر.عیسائی قوم کو اپنی آخری زمانہ کی ترقی پر ناز ہوگا اب فرماتا ہے کہ وہ اپنی حکومتوں اور
Page 530
شان وشوکت پر بہت ناز کریں گے اورسخت بے دین ہوں گے کیونکہ ظالمٌ لِنفسہٖ کایہی مطلب ہوتاہے.اورپھر ان کویہ خیال ہوگا کہ ہماری حکومت کبھی تباہ نہ ہوگی.اس جگہ جنت کالفظ استعمال کیاگیا ہے.حالانکہ باغ دوتھے.کیونکہ گومسیحی قو م کوناز اپنی پہلی تاریخ پر بھی ہے.مگراصل ناز ان کو آخری زمانہ کی ترقی پر ہے.اوراسلام کے مقابل پر وہ اسی کو پیش بھی کرتے ہیں.اس لئے اب اس جگہ سے دوباغوں کا ذکر ترک کرکے سب مفرد کے صیغے ہی استعمال کئے گئے ہیں.جنتین کی جگہ جنت کہنے سے یہ بھی مراد ہوسکتی ہے.کہ ان دونوں جنتوںکو ایک لحاظ سے ایک ہی سمجھنا چاہیے کیونکہ درحقیقت یہ ترقی ایک ہی قوم کی ہے گوایک وقفہ پڑ جانے کی وجہ سے دوحصوں میں تقسیم ہوگئی ہے.ان معنوں کے روسے میرے اس خیال کی تائید ہوتی ہے.جومیں اوپر بیان کرآیاہوں کہ کِلْتَا کے لئے باوجود تثنیہ کی ضمیر کے استعمالی کی اجازت ہونے کے جومفرد کی ضمیر پھیری گئی ہے اس سے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے.کہ من جہۃٍ وہ دونوں باغ ایک ہی باغ سمجھے جانے چاہئیں.وَّ مَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآىِٕمَةً١ۙ وَّ لَىِٕنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ اورمیں نہیں سمجھتاکہ وہ (موعودہ)گھڑی (کبھی)آنے والی ہے.اوراگر(بالفرض)مجھے میرے رب کی طرف لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۰۰۳۷ لوٹا(بھی)دیاجائے تومیں (وہاں بھی )یقیناًاس سے بہتر ٹھکانا پائوں گا.حل لغات.ظَنٌّ اَظُنُّ ظَنَّ سے مضارع متکلم کاصیغہ ہے.اورظَنَّ الشَّیْءَ کے معنی ہوتے ہیں : عَلِمَہُ کسی چیز کو جاننا.وَاسْتَیْقَنَہُ کسی چیز کے متعلق یقین کرلیا.وَتَأْتِیْ ظَنُّ لِلدَّلَالَۃِ عَلَی الرُّجْحَانِ.اوربعض اوقات راجح خیال کوظاہر کرنے کے لئے بھی ظَنَّ کافعل استعمال کرتے ہیں (اقرب)پس مَااَظُنُّ کے معنی ہوں گے میں یقین نہیں کرتا.میں نہیں سمجھتا.الساعۃ اَلسَّاعَۃُ کے لئے دیکھو سورہ ہذاآیت نمبر ۲۲.منقلبًامُنْقَلَبًایہ اِنْقَلَبَ سے مصدرمیمی ہے اورظرف مکان بھی ہے.اِنْقَلَبَ کے معنی ہیں اِنْکَبَّ الٹ گیا.رَجَعَ.لوٹا(اقرب)
Page 531
تفسیر.اس میں اشارہ کیا ہے کہ اس قوم میں دوخیالات کے لوگ ہوں گے ایک تووہ جو قیامت کے قائل نہ ہوںگے.سب کچھ اسی دنیا کو سمجھیں گے.اوردوسراگروہ قیامت کاقائل ہوگا.مگراس کایہ خیال ہوگا.کہ اگلے جہان کے انعامات بھی انہی کے لئے مقرر ہیں.چنانچہ یہی حال مسیحیوں کاہے.کچھ ان میں سے اس امر کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں.بلکہ قومی ارتقاء کے معنی ہی جنت کے ہیں اوریہ مسیحیوں کومل گئی ہے.اورمل جائے گی اور بعض بعث بعد الموت کے تو قائل ہیں.لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ مسیح نے ہمار ے گناہ اٹھالیئے ہیں اوردوسروں کے گنا ہ اٹھانے والا کوئی نہیں.اس لئے ہم تونجات پا جائیں گے دوسرے سب لوگ دوز خ میں جائیںگے.قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ اس کے ساتھی نے اس سے سوال وجواب کرتے ہوئے کہا (کہ )کیاتونے اس (ہستی) کاانکار کردیاہے جس نے مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًاؕ۰۰۳۸ تجھے (اوّلاً)مٹی سے (اور)پھر نطفہ سے پیدا کیا.(اور)پھر اس نے تجھے پوراآدمی بنایا.حلّ لُغَات.نطفۃ نُطْفَۃٌکے معنی کے لئے دیکھو نحل آیت نمبر ۵.سَوَّاکَ رَجُلًا سَوَّی الشَّیْءَ کے معنی ہیں جَعَلَہٗ سَوِّیًا کسی چیز کوٹھیک اورمکمل بنادیا (اقرب) پس سَوّٰىكَ رَجُلًاکے معنی ہوں گے تجھے پورامکمل آدمی بنادیا.سَوَّی الشَّیْءَ کے معنی ہیں جَعَلَہٗ سَوِیًّا اس کو سویّ یعنی بےعیب وبے نقص بنادیا.غُلَامٌ سَوِیٌّ:اَیْ لَادَاءَ بِہٖ وَلَا عَیْبَ.جب یہ لفظ انسان کے لئے بولاجائے.تواس کے معنے ہوتے ہیں کہ جسمانی طورپر بھی اس میں کوئی نقص نہیں ہے اوراخلاقی لحاظ سے بھی اس میں نقص نہیں ہے.چنانچہ غُلَامٌ سَوِیٌّ ٌّ ایسے لڑکے پر بولتے ہیں جس میں اخلاقی اور جسمانی کوئی نقص اورعیب نہ ہو.وَمِنْہُ رَزَقَکَ اللہُ ولدًاسویًّا.اورانہی معنوں میں یہ فقرہ بطور دعا کے کہاجاتاہے.کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بے عیب لڑکا عطا فرماوے(اقرب)
Page 532
تفسیر.یہ تمثیلی زبان میں مسلمانوں کی طرف سے جواب دیاہے.یعنی اس مثال میں ایک اوربھی شخص تھا.اس نے اس تکبر کرنے والے کونصیحت کی.اورکہا کہ کیا تم خدا تعالیٰ کاانکار کرتے ہو.جس نے تم کوپیدا کیا.پھر ادنیٰ حالت سے ترقی دے کر کمال تک پہونچا دیا.یعنی تمہاری حالت عملاً اللہ تعالیٰ کے انکار کے متراد ف ہے.ورنہ خدا تعالیٰ پر حقیقی ایمان رکھتے ہوئے کوئی ایسے خیالات نہیں رکھ سکتا جیسے کہ تمہارے ہیں.قرآن کریم کایہ عام طریق ہے کہ جب کسی کو یہ کہتاہے.کہ اپنی ترقی پر غرورنہ کر تواس کی ابتدائی حالت کی طرف توجہ دلاتاہے.جس طرح مسلمانوں کوکہا ہے کہ تم مایوس نہ ہو.یہ جواس وقت کی ترقی یافتہ قومیں ہیں یہ بھی پہلے کمزورتھیں.اب عیسائیوں کو فرمایا.کہ تم یہ خیال نہ کرو.کہ مسلمان کمزورہیں.تم اپنی پہلی حالت کو دیکھو کہ وہ کس قدر کمزور تھی.اور جسمانی پیدائش بھی انسان کی مٹی اورپھر نطفہ سے ہی ہوتی ہے.اس تمثیل میں دونوں اشخاص کی گفتگوکے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ وَھُوَ یُحَاوِرُہٗ جس سے اس طرف اشارہ کیا ہے.کہ ان دونوں قوموں میں مباحثات ہوں گے.اورمباحثات کے دوران میں مسیحی لوگ مسلمانوں کی کمزور ی اوراپنی قوت کو اپنے سچاہونے کی دلیل قراردیا کریں گے.لٰكِنَّاۡ هُوَ اللّٰهُ رَبِّيْ وَ لَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا۰۰۳۹ (تمہاراتویہ حال ہے )لیکن (میں تویہ کہتا ہوں کہ)حق تویہ ہے کہ اللہ (تعالیٰ)ہی میرارب ہے اورمیں کسی کو (بھی ) اپنے رب کاشریک نہیں بناتا.تفسیر.یعنی میراسہارااوراطمینان اپنی تدبیر پر نہیں مجھے توجوکچھ دے گا خدا تعالیٰ ہی دے گا.ہمارے پاس توکچھ بھی نہیں ہے.اورہمیں اسی نہ ہونے پر فخر ہے کہ تازہ بتازہ خدا تعالیٰ کے نشانات دیکھتے رہتے ہیں.وَ لَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا میں کیالطیف بات بیان فرمائی ہےکہ خدا تعالیٰ نے تم کودیاہے.اورپھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہو.لیکن خداتعالی نے مجھے دنیاکامال نہیں دیا.پھر بھی میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا.یعنی شبہ تومجھے ہوسکتاتھا.کہ شائددوخداہوں.کہ تمہارے خدا نے تم سے حسن سلوک کیا.اور میرے خدا نے نہ کیا.مگر میں توغربت میں بھی ایک ہی خدا کا ماننے والاہوں.
Page 534
مصیبت اَلْعَجَاجُ.غبار.اَلْـجَرَادُ.ٹڈی دل.اَلنَّارُ.آگ (تاج) صعیدًا صَعِیْدًاکے معنی کے لئے دیکھو سورۃ ہذاآیت نمبر ۹.زَلَقًا.اَلزَّلْقُ :مَوْضِعُ الزَّلَقِ لَایَثْبُتُ عَلَیْہ قدمٌ پھسلنے کی جگہ جہاں پائوں جم نہ سکے.اَرْضٌ زَلَقٌ اَیْ مَلْسَاءٌ لَیْسَ بِھَاشَیْءٌ.چٹیل میدان بے آب وگیاہ زمین (اقرب) تفسیر.اس آیت میں بھی جنت کا لفظ جوایک باغ پر دلالت کرتاہے استعمال ہواہے.اوراس کے بعد يُرْسِلَ عَلَيْهَا فرمایا ہے عَلَیْھِمَا نہیں فرمایا.کیونکہ ایک باغ اسلامی زمانہ سے پہلے ہلاک ہوچکاتھا اس پر فخر تواس رنگ کا تھا.جیسے کہ لوگ اپنے آباء کی بڑائی پر فخر کرتے ہیں.اصل فخر موجودہ زمانہ کے باغ پرہے.اس لئے فرمایا کہ اگر تومجھے ادنیٰ حالت میں دیکھتا ہے اوراس پرنازاں نہ ہو.کیونکہ یہ بات ناممکن نہیں.کہ میرارب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے.اورصرف یہی نہیں بلکہ آسمانی عذاب نازل کرکے تیرے باغ کو جلادے.اورتیرے ہمیشہ حکومت کر نے کے دعاوی دھرے کے دھرے رہ جائیں.اس جگہ صَعِيْدًا زَلَقًا کے الفاظ آئے ہیں.یہ وہی لفظ ہیں جو شروع سور ۃ میں خدا تعالیٰ کابیٹابنانے والوں کی نسبت آچکے ہیں جس سے ظاہرہوگیا.کہ اس قوم کے متعلق اس جگہ مثال بیان کی گئی ہے.یاجوج ماجوج سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہ ہوگی مِنَ السَّمَآءِ میں یہ بتایا ہے.کہ زمینی تدابیر سے اس قوم کامقابلہ نہ ہوسکے گا چنانچہ یاجوج ماجوج کے متعلق جومسیحیت کی دنیاوی ترقی کے دوظہور ہیں لکھا ہے کہ لَایَدَانِ لِاَحَدٍ بِقِتَالِھِمْ (مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال) کہ ان سے لڑنے کی کسی کوطاقت نہ ہوگی.ان کامقابلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا.اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا۰۰۴۲ یااس کاپانی خشک ہوجائے (اور)پھرتواس کی تلاش کی (بھی)طاقت نہ پائے (چنانچہ ایسا ہی ہوا) حلّ لُغَات.غَوْرًا.غَارَالْمَاءُ غَوْرًا کے معنی ہیں ذَھَبَ فِی الْاَرْضِ وَسَفَلَ فِیْھَا پانی زمین میں جذب ہوکر نیچے چلاگیا.اَلْغَوْرُ غَارَ کامصدر ہے.نیز اس کے معنی ہیں اَلْمَاءُ الْغَائِرُ ایساپانی جو زمین میں جذب ہوکر خشک ہوگیاہو(اقرب)
Page 535
تفسیر.اس آیت سے ظاہرہوگیا کہ نھر سے مراد مسیحی باغ کاپانی نہ تھا.کیونکہ اس آیت کی نسبت فرماتا ہے کہ اس کے باغ کاپانی زمین میں ہی غائب ہوجائے.اورنہروںکاپانی زمین میں غائب نہیں ہوتا.بلکہ باہر سے آتاہے.پس ا ن باغوں کاپانی الگ تھا.جوان باغوں میں موجود تھا.اوراس کے زمین میں ہی غائب ہونے کی خبر دی گئی ہے یعنی اس قوم کی اندرونی طاقتیں تبا ہ ہوجائیں گی اوروہ ذہنی قوتیں جو پہلے باغوںکو آباد کرنے کاموجب تھیں.خشک چشموں کی طرح ہوکر باغ کے اجڑنے کاموجب بن جائیں گی.وَ اُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَاۤ اَنْفَقَ فِيْهَا اوراس کے (تمام )پھلو ں کوتباہ کردیاگیا.اوروہ اس حال میں کہ وہ (یعنی باغ)اپنی ٹٹیوں پر گراہواتھا اس وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ لَمْ (مال)پرجو اس نے اس (باغ کی ترقی)کے لئے خرچ کیاتھا اپنے دونوں ہاتھ ملنے لگا اورکہنے لگا(کہ ) اُشْرِكْ بِرَبِّيْۤ اَحَدًا۰۰۴۳ اے کاش میں کسی کو اپنے رب کاشریک نہ بناتا.حلّ لُغَات.اُحِیْطُ بِثَمَرِہِ:اُحِیْطَ بِہِ کے معنی ہیں.دَنَاھَلَاکُہُ.اس کی ہلاکت کا وقت آپہونچا.(اقرب) نیز جب محاورہ بولیں.اَلسَّنَۃُ الْمُجْدِبَۃُ:الشَّدِیْدَۃُ تُحِیْطُ بِالْاَمْوَالِ تواس کے یہ معنی ہوتےہیں تُھْلِکُھَا کہ قحط سالی نےمالو ں کوتباہ کردیا (تاج)پس اُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کے پھل کوتباہ کر دیا گیا.اَصْبَحَ یُقَلِّبُ کَفَّیْہِ اَیْ یَتَنَدَّمُ جب اَصْبَحَ یُقلِّبُ کامحاور ہ بولیں تویہ مراد ہوتی ہے کہ وہ نادم ہوگیا(اقرب) خاویۃٌ خَاوِیَۃٌخَوِیَ یَخْوَی یاخَوَی یَخْوِیْ سے اسم فاعل مؤنث کاصیغہ ہے.خَوَتِ الدَّارُ کے معنی ہیں اَقْوَتْ وَسَقَطَتْ وَتَھَدَّمَتْ مکان اجڑ گیا.گرگیا منہدم ہوگیا.خَوِیَتِ الدَّارُ کے معنی ہیں خَلَتْ مِنْ اَھْلِھَا گھر رہنے والوں سے خالی ہوگیا.(اقرب)
Page 536
عُرُوشٌ.عُرُوْشٌ عَرْشٌ کی جمع ہے اوراَلْعَرْشُ مِنَ الْبَیْتِ کے معنی ہیں سَقْفُہُ گھر کی چھت (اقرب)پس خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا کے معنی ہوں گے کہ وہ اپنی چھتوں پر گراہواتھا.تفسیر.اُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ یعنی جونتائج پہلے ان کی محنتوں کے نکلے تھے پھر نہ نکلیں گے.اوروہ افسوس کرنے لگ جائیں گے کہ اس قدر روپیہ خرچ کرکے جوسامان تیار کئے تھے.اب کسی کام کے نہیں رہے.جواقوام دنیوی شان وشوکت پر روپیہ خرچ کرتی ہیں ان کے اند ر تباہی کے وقت سخت حسرت پیداہوتی ہے.کیونکہ وہی عمارتیں جن پر وہ فخر کرتے تھے.اب ان کی مرمتیں بھی ان کے لئے مشکل ہوجاتی ہیں.لیکن جوقومیں اپنے اموال اپنی قوم کی علمی اوراخلاقی ترقی کے لئے خرچ کرتی ہیں.ان کاخرچ ان کے لئے کبھی حسرت کا موجب نہیں ہوتا.وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا کہہ کر بتایا کہ ان میں بڑی بڑی عمارتیں تیارکرنے کامرض ہوگا.وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَاباغ کے لئے نہیں آسکتا.اس وقت ان میں افسوس پیدا ہوگاکہ کیوں شرک کیا اورتوحید کوقبول کرکے اورناصح کی نصیحت کومان کر ہم اس عذاب سے نہ بچ گئے.خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَامیں ا س طرف بھی اشارہ ہے کہ ان پرایسے عذاب آئیں گے کہ شہر برباد ہوجائیں گے اورعمارتیں گرادی جائیں گی.وَ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ اور(اس وقت )کوئی جماعت بھی اس کے ساتھ نہ ہوئی جواللہ (تعالیٰ)کوچھوڑ کر اس کی مددکرتی.اورنہ وہ (اس مُنْتَصِرًاؕ۰۰۴۴ کاکوئی )انتقام ہی لے سکا.حلّ لُغَات.اَلْفِئَۃُاَلْفِئَۃُ الطَّائِفَۃُ.گروہ.اَلْجَمَاعَۃُ.جماعت (اقرب) مُنْتَصِرٌ.مُنْتَصِرٌ اِنْتَصَرَ سے اسم فاعل کاصیغہ ہے.اوراِنْتَصَرَ کے معنی ہیں اِنْتَقَم مِنْہُ اس سے انتقام لیا.اِنْتَصَرَ عَلَیْہ: اِسْتَظْھَرَ اس پر غالب آیا (اقرب) پس مُنْتَصِرٌ کے معنی ہیں انتقام لینے والا.تفسیر.یعنی اس قوم کو مسیح کی تائید پر بہت بھروسہ ہوگا.لیکن اس دن مسیح بھی ان کی کوئی مدد نہ
Page 537
کرسکیں گے.هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ١ؕ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اس موقعہ پر مد داللہ (تعالیٰ)کی ہی(مفید)ہوتی ہے.جومعبودحقیقی ہے.اور وہ بدلہ دینے میں(بھی)سب سے عُقْبًاؒ۰۰۴۵ اچھا ہے اور(اچھا) انجام (پیداکرنےکی)روسے بھی سب سے اچھا ہے.تفسیر.اس آیت سے صاف ظاہرہوگیا.کہ اس جگہ پیشگوئی کا ذکر ہے.کیونکہ فرماتا ہے.اس موقعہ پر حکومت اللہ تعالیٰ ہی کی ہوجائے گی اوروہ ان لوگوں پر فضل کرے گا جواس کے موحد بندے ہوں گے.اوردنیا کی بجائے آخرت کی طرف توجہ کرنے والے ہوں گے.وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ اورتو ان کے سامنے اس ورلی زند گی کی حالت(بھی کھول کر )بیان کر(کہ وہ )اس پانی کی طرح (ہے)جسے ہم نے السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا بادل سے برسایاپھر ا س میں زمین کی روئیدگی مل گئی.پھر(آخر)وہ (بھوسے کا)چورابن گئی.جسے ہوائیں اڑاتی تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ١ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا۰۰۴۶ (پھر تی) ہیں اوراللہ (تعالیٰ)ہربات پر خوب قدر ت رکھنے والا ہے.حلّ لُغَات.اِختلط.اِخْتَلَطَ کے معنی ہیں اِمْتَزَجَ مل گیا.(اقرب) الھشیمُ.ھَشِیْمٌ کے معنی ہیں اَلْمَھْشُوْمُ ٹوٹاہوا نَبْتٌ یَابِسٌ مُتَّکَسِّرٌ خشک شکستہ پودہ یَابِسُ کُلِّ کَلَأٍ وَشَجَرٍ.ہرخشک گھاس درخت.(اقرب) تَذْرُوْہُ :تَذْرُوْہُ ذَرَاَسے مضارع مونث غائب کاصیغہ ہے.اور ذَرَتِ الرِّیْحُ التُّرَابَ کے معنی ہیں
Page 538
فَرَّقَتْہُ وَاَطَارَتْہُ وَاذْھَبَتْہُ ہوانے مٹی کواڑاکربکھیردیا (اقرب)پس تَذَرُوْہُ کے معنی ہوں گے اسے ہوائیں اڑاتی ہیں.مُقْتَدِرًا مُقْتَدِرٌ اِقْتَدَرَ(جوقَدَرَسے نکلاہے )سے اسم فاعل ہے اِقْتَدَرَ عَلَیْہِ کے معنی ہیں قَوِیَ عَلَیْہِ وَتَمَکَّنَ مِنْہُ.اس پر پوری قدرت پائی.اس پر قابو پالیا (اقرب)پس مُقْتَدِرًاکے معنی ہوں گے خوب قدرت والا.تفسیر.سابق تمثیل کے مضمون کی مزید وضاحت اس زندگی کی مثال میں سابق تمثیل کے مضمون کو ایک اور تمثیل سے واضح فرمایاگیا ہے.فرماتا ہے کہ دنیوی زندگی پہلے نہایت خوبصورت نظرآتی ہے.مگراس کاانجام بڑابدنماہوتاہے.اوراس کے بالمقابل دینی زندگی پہلے بظاہر بدنماہوتی ہے.مگر اس کاانجام نہایت خوش شکل ہوتاہے.جب مادی پانی آسمان سے اترتاہے توکسی قدر سبزی اس سے پیداہوتی ہے.اورٹہنیاں کثرت کی وجہ سے ایک دوسری میں گھسی جاتی ہیں.لیکن پھر سب سبزہ خشک ہوکر ہوامیں اڑتاپھر تاہے.لیکن اس کے مقابل پر روحانی پانی سے جوکھیتی تیا رہوتی ہے.و ہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتی.بظاہر اس مثال پر یہ اعتراض پڑتا ہے.کہ کھیتی توخشک ہوکر ہی کھانے کے کام آتی ہے.مگراس جگہ کھانے والے کی تمثیل نہیں دی.کھیتی کی تمثیل دی ہے.بتایاہے کہ دنیاوی ترقی کے وقت قومیں بہت لہلہاتی نظر آتی ہیں.مگرزوال کے وقت ان کوکوئی پوچھتابھی نہیں.اس کے برخلاف جوقومیں دین کی طر ف توجہ کرتی ہیں.اگلے جہان میں توان کوعزت ملے گی سوملے گی.اس دنیا میں بھی ان کی عزت ہمیشہ قائم رہتی ہے.نوح کی کوئی قوم باقی نہیں.مگردیکھو نوح ؑ کی آج بھی عزت ہے.یہی حال ابراہیم کاہے.یہودی ذلیل ہوئے ہیں مگرموسیٰ کی عزت بدستورہے.قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی دیناوی فتوحات جاتی رہیں.لیکن ان کی دینی خدمات کی وجہ سے آج بھی ان میں سے ادنیٰ سے ادنیٰ کے نام پر جانیں قربا ن کرنے والے لوگ موجود ہیں.
Page 539
اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا١ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ مال اوربیٹے اس ورلی زندگی کی زینت ہیں.اورباقی رہنے والے نیک (اورمناسب حال )کام (ہی جوان چیز وں الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا۰۰۴۷ سے لئے جائیں)تیرے رب کے نزدیک بدلہ کے لحاظ سے(بھی)بہترہیں.اورامید کے لحاظ سے (بھی)بہتر ہیں حلّ لُغَات.اَلْاَمَلُ.اَلْاَمَلُکے لئے دیکھو رحجر آیت نمبر ۴.اَ لْاَمْلُ وَالْاَمْلُ اس کی جمع اٰمَالٌ ہے.اوراَلْاَمَلُ کے معنے ہیں.الرَّجَاءُ.امید.تَاَمَّلْتُ الشَّیْءَ اَیْ نَظَرْتُ اِلَیْہِ مُسْتَثْبِتًالَہٗ.تَأَ مَّلْتُ الشَّیْءَ کے معنے ہیںاسے غورسے دیکھا.ٹکٹکی لگا کر دیکھا.(اقرب) تفسیر.اس جگہ پر بھی تشریح فرما دی کہ نَبَاتُ الْاَرْضِ سے کیامراد ہے.پہلی تمثیل میں باغ بیان کرکے اس کی تشریح میں اس صاحب الجنۃ کایہ قول بیان کیاتھا اَنَا اَکْثَرُ مِنْکَ مَالًاوَّاَعَزُّ نَفَرًا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے.اورمیری تعداد بھی زیادہ ہے.اس جگہ پر نَبَاتُ الْاَرْضِ بیان فرماکر اس کی تعبیر میں فرمایا.اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا.جس سے ظاہر ہے کہ جنت سے یہی مراد تھی.اس آیت میں بتایاہے کہ مال اوراولاد بے شک دنیاکی زینت ہیں لیکن اگرانہیں صحیح طورپر استعمال کیاجائے یعنی دین میں مال خرچ ہو ں.اوردین کی خدمت کے لئے اولاد لگادی جائے.توپھر اللہ تعالیٰ ان کوبھی دوام بخش دیتاہے روپیہ خرچ ہو جاتا ہے لیکن اس کانیک اثر باقی رہ جاتا ہے اولاد مرجاتی ہے لیکن ان کا ذکر خیر بھی باقی رہ جاتاہے.اوران کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا ذکر خیر بھی زندہ رہتاہے.اَلْبٰقِیٰتُ الصّٰلِحٰتُ کُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ نیک اوراچھے کام باقیات صالحات کہلاتے ہیں.آیت خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ الخکے دو معنی خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا اس کے دومعنی ہیں (۱)نیک کام کادنیامیں نتیجہ نکلتاہے اوراس کے متعلق آئندہ بھی اچھی امیدیں ہوتی ہیں.گویاثواباً دنیاکے نتیجہ کے متعلق ہے.اور اَمَلًا آخرت کے متعلق ہے.(۲)ثوابًا سے مراد خود اس عمل کرنے والے کی ذات کے متعلق بہترنتائج کاپیداہونا ہے.اوراملاًسے مراد آئندہ نسل کے لئے بہترین امیدوںکاہوناہے.مطلب یہ کہ نیک کاموں کانتیجہ تم کو بھی نیک ملے گا.اور تمہاری اولادوں کو بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ و ہ نیک کی اولاد کوبھی فائدہ پہونچاتاہے.
Page 540
وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً١ۙ وَّ اور(اس دن بھی ان کے بہترنتائج نمودار ہوںگے)جس دن ہم ان پہاڑوں کو (اپنی اپنی جگہ سے)چلادیں گے حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًاۚ۰۰۴۸ اورتوسب (اہل) زمین (کوایک دوسرے کے مقابلہ میں)نکلتاہوادیکھے گا.اورہم ان (سب)کواکٹھاکریں گے اوران میں سے کسی کو( بھی باقی) نہیں چھوڑیں گے.حلّ لُغَات.بَارِزَۃٌ بَارِزَۃٌ بَرَزَ(یَبْرُزُ.بُرُوْزًا)سے اسم فاعل مؤنث کاصیغہ ہے.بَرَزَکے معنی ہیں خَرَجَ نکل آیا (اقرب)پس بَارِزَۃٌ کے معنی ہوں گے نکلنے والی.حَشَرْنٰھُمْ حَشَرْنٰھُمْ حَشَرَ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے اورحَشَرَ کے لئے دیکھو سورئہ حجرآیت نمبر ۲۶.حَشَرَ النَّاسَ کے معنے ہیں جَمَعَہُمْ.لوگوں کو جمع کیا.وَیَوْمُ الحَشْرِ:یَوْمُ الْبَعْثِ وَالْمَعَادِ وَھُوَ مَأخُوْذٌ مِنْ حَشَرَ الْقَوْمَ اِذَا جَمَعَـہُمْ.اوریوم البعث کو یوم حشر انہی معنوں کی روسے کہتے ہیں کہ اس دن اگلے پچھلے لوگوںکو جمع کیا جائے گا.وَالْحَاشِرُ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ نَبِیِّ المُسْلِمِیْنَ.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ایک نام حاشر بھی ہے.(اقرب) لم نغادر نُغَادِرُ غَادَرَ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے اورغَادَرَہُ کے معنی ہیں تَرَکَہٗ وَاَبْقَاہُ اس کوچھوڑ دیا اورباقی رکھا (اقرب)پس لَمْ نُغَادِرُ کے معنی ہوں گے کہ ہم باقی نہیں رکھیں گے.ہم نہیں چھو ڑیں گے.تفسیر.جبل کے معنی بڑے آدمی کے بھی ہوتے ہیں اورسیّرکے معنی چلانے کے (اقرب).اس جگہ جبال سے مراد بڑے لوگ ہی ہیں.کیونکہ اس جگہ آدمیوں کا ذکر ہے پہاڑوں دریائوںکا ذکر نہیں.اوربتایاگیا ہے کہ یہ سب پیشگوئیاںاس دن پوری ہوںگی.جب بڑے بڑے لوگ جنگوں کے لئے نکل کھڑے ہوں گے.اورتوساری زمین کو یعنی سب اہل زمین کودیکھے گاکہ جنگ کے لئے ایک دوسرے کے مقابل پر کھڑے ہوجا ئیں گے اورایسی جنگ ہوگی کہ گویا ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا.اس واقعہ کی طرف انجیل میں بھی اشارہ ہے.حضر ت مسیح فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں قوم قو م پر اور بادشاہت بادشاہت پر چڑھائی کرے گی.‘‘(متی باب ۲۴آیت ۷)
Page 541
اَلْاَرْضَ سے مراد اہل ارض اَلْاَرْضَ سے مراد اہل ارض(اہل زمین)ہیں.عربی زبان کامحاورہ ہے کہ بعض دفعہ مضاف کو محذوف کردیاجاتاہے جیسا کہ سورئہ یوسف میں آتاہے وَ سْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا(یوسف:۸۳)یہاں القریۃ اورالعیر سے مراد اہل قریہ اوراہل عیر ہیں.الارض ،الجبل سے مراد ڈکٹیٹرز اور ڈیماکریسز ہو سکتا ہے کہ اَلْاَرْضَ سے ادنیٰ طبقہ کے لوگ مراد ہوں.اوراَلْجِبَالَ سے مراد بڑے لوگ یعنی اس دن ایک طرف سے جبال یعنی بڑے لوگ یادوسرے لفظوں میں ڈکٹیٹرز نکلیں گے.اور دوسری طرف سے ارض یعنی ڈیماکریسز کے حامی اورحکومت عوام کے نمائندے نکلیں گے.اورآپس میں خوب جنگ ہوگی.حَشَرْنٰهُمْ.حَشَرَ کے معنی کھڑاکردینے کے ہوتے ہیں.اورحَشْرٌ لشکر کے لئے بھی آتاہے.کیونکہ وہ بھی سامنے کھڑاہوتاہے.فرمایاہم ان سب کو ایک دوسرے کے مقابل پر کھڑاکردیںگے اورسب کوسزادیں گے.وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا١ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا اوروہ صف باندھے ہوئے تیرے رب کے سامنے پیش کئے جائیں گے (اوران سے کہا جائےگاکہ )تم (اب) كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۭ١ٞ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ یقیناً( اسی طرح بحالت ناچارگی )ہما رے پاس آئے ہو جس طرح (کی حالت میں )ہم نے تمہیں پہلی بارپیدا کیاتھا لَكُمْ مَّوْعِدًا۰۰۴۹ (اور تم یہ امید نہیں رکھتے تھے )بلکہ تمہیں دعویٰ تھا کہ ہم تمہا رے لئے کوئی وعدہ (کے پوراہونے)کی ساعت مقررنہیں کریں گے.تفسیر.و ہ اپنے رب کے حضور صفیں باندھ کر کھڑے کئے جائیں گے.یعنی اللہ تعالیٰ کافیصلہ ان کے متعلق جاری کیا جائے گا خداکے حضور پیش ہونے میں باطنی صفیں باندھنا ہی مراد ہے ظاہری صفوں کاہونامرا دنہیں.جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تباہی کافیصلہ کرتا ہے تووہ اس کی قیامت ہی ہوتی ہے.لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۭ١ٞ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا تم ہمارے پاس آئے ہو.جیسا
Page 542
کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا.یعنی پھر تم ماتحت ہوگئے ہو کیاتمہاراخیال تھا کہ ہم نے تمہارے لئے کوئی وعدہ مقرر نہیں کیاتھا.یعنی تمہاری تباہی کا وقت مقرر نہ تھا.اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ یہ دوسری تمثیل پہلی کی شرح ہے.کیونکہ پہلی تمثیل میں بھی یہ کہا گیاتھا.مَااَظُنُّ اَنْ تَبِیْدَ ھٰذِہٖ اَبَدًا.وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ اور(ان کے اعمال کی )کتاب (ان کے سامنے )رکھ دی جائے گی.پس (اے مخاطب)توان مجرموں کو اس کی وجہ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ سے جواس میں (لکھا)ہوگاڈرتے دیکھےگا.اور(اس وقت )وہ کہیں گے کہ اے (افسوس)ہمار ی تباہی (سامنے لَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا١ۚ وَ وَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا١ؕ وَ کھڑی ہے )اس کتاب کوکیا (ہوا) ہے (کہ )نہ کسی چھوٹی بات کو اس کااحاطہ کئے بغیر چھوڑتی ہے اورنہ کسی بڑی لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًاؒ۰۰۵۰ بات کو اورجوکچھ انہوں نے کیا (ہوا)ہوگا.اُسے (اپنے سامنے )حاضرپائیں گے.اورتیرارب کسی پرظلم نہیں کرتا.حلّ لُغَات.مُشفقین اَشفَقَ سے اسم فاعل مُشْفِقٌ آتاہے.اورمُشْفِقُوْنَ اس کی جمع ہے اَشْفَقَ عَلَیْہِ کے معنی ہیں : خَافَ وَحَاذَرَ.ڈرااوراس نے بچائوکیا (اقرب) اَحْصٰھَا.اَحْصَی الشَّیْءَ اِحْصَاءً کے معنی ہیں عَدَّہُ اسے شمار کیا (اقرب) تفسیر.وضع کتاب کے معنی وُضِعَ الْكِتٰبُ.کتا ب کے رکھاجانے کے معنی یہ ہیںکہ وہ ان میں جاری ہوجائے گی.یعنی اس کافیصلہ نافذ ہوجائے گا.وَضَعْنَا السَّیْفَ فِیْھِمْ کے معنی ہوتے ہیں کہ تلوار نے ان میں اپناکام کرناشروع کردیا.یعنی خوب قتل کرنے لگ گئی.فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ.یعنی ان اقوام کے دل سے وہ خیال مٹ جائے گاکہ ہماری حکومت ہمیشہ رہے گی بلکہ دلوں
Page 543
میں ڈرپیداہوجائے گا.کہ جس تہذیب پر ہم کو اس قدرناز تھا وہ تباہ ہونے کوہے.يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِسے اس طرف اشار ہ ہے.کہ تمام گزشتہ غلطیوں کی سز اایک ایک کرکے ملنی شروع ہوجائے گی.اوران کے دل محسوس کریں گے کہ ا س دنیاکاحاکم خداہے.جوانسانی اعمال کو بغیر نتیجہ کے نہیں چھوڑتا اوروہ سب اپنے اعمال کانتیجہ بھگتیں گے.آخر میں یہ بتایاکہ گوانجام بڑاتلخ ہوگا.مگریہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہ ہوگا.بلکہ اعمال کے مطابق جزاہوگی.وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ١ؕ اور(اس وقت کو بھی یاد کرو)جب ہم نے فرشتوںکوکہاتھا(کہ )تم آدم کےساتھ(ساتھ)سجد ہ کروتوانہوںنے كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ١ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ (تواس حکم کے مطابق )سجدہ کیا.مگرابلیس نے (نہ کیا )وہ جنوں میں سے تھاپھراس نے اپنے رب کے حکم کی وَ ذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ١ؕ بِئْسَ نافرمانی کی.توکیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اوراس کی نسل کو (اپنے )دوست بناتے ہو.حالانکہ و ہ تمہارے دشمن ہیں.لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا۰۰۵۱ ظالموں کے لئے وہ (یعنی شیطان خدا تعالیٰ کا)بدل ہونے کے لحاظ سے بہت ہی بُراہے حلّ لُغَات.لِاٰدَمَ لِاٰ دَمَ ل بمعنی مَعَ ہے.تفصیل کے لئے دیکھو سورئہ بنی اسرائیل آیت نمبر ۶۲.سَجَدُوْا سَجَدُوْا سَجَدَ سے جمع کاصیغہ ہے.تشریح کے لئے دیکھو حجرآیت نمبر ۳۱.اَلسُّجُوْدُ.اَلتَّذَلُّلُ سجود کے معنی تذلل اورماتحتی کے ہیں.(مفردات) وَقَوْلُہٗ اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ قِیْلَ اُمِرُوْا بِالتَّذَلُّلِ لَہٗ وَ الْقِیَامِ بِمَصَالِحِہِ وَ مَصَالِحِ اَوْلَادِہِ.آیت اُسْجُدُوْا لِاَدَمَ میںفرشتوںکو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدم کے ماتحت چلیں.اوراس کی مدد کریں اوراس کی اولاد کے لئے ممدّو معاون بنیں.وَقَوْلُہ ادْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًااَیْ مُتَذَلِّلِّیْنَ مُنْقَادِیْنَ.اورقرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ تم اس دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل
Page 544
ہوجائو.اس کے معنے بھی یہی ہیں کہ تم فرمانبرداری کرتے ہوئے جائو.(مفردات) ابلیس اِبْلِیْسَ کے لئے دیکھو حجرآیت نمبر ۳۲و بنی اسرائیل آیت نمبر ۶۲.اَلْجِنّ کے لئے دیکھو حجر آیت نمبر ۳۸.جَنَّ یَجُنُّ جَنًّاوَ جُنُوْنًا کے معنے ہیں.سَتَرَ ہٗ وَاَظْلَمَ عَلَیْہِ پردہ ڈال دیااوراندھیراکردیا جَنَّ الَّیْلُ:اَظْلَمَ وَاخْتَلَطَتْ ظُلْمَتُہٗ.رات کی تاریکی چھا گئی.وَجَنَّ الْجَنِیْنُ فِی الرَّحِمِ: اِسْتَتَرَ.جنین رحم میں پوشیدہ ہوگیا.وَالْجَانُّ اسم فاعل اور جانّ اسم فاعل ہے یعنی اندھیرا کردینے والا.یاپوشیدہ ہوجانے والا.وَاِسْمٌ جَمْعٍ لِلْجِنِّ.اوریہ جنّ کی اسم جمع بھی ہے.حُیَّۃٌ بَیْضَاءُ کَحَلَاءُ الْعَیْنِ لَاتؤْذِیْ.اوراس سفیدسانپ کو بھی جو سرمگین آنکھوں والاہو جانّ کہتے ہیں.ایسے سانپ میں زہر نہیں ہوتااوروہ کاٹتا نہیں (اقرب) وَالْجَانُ اَبُوالْجِنِّ اورجنّوں کے مورث اعلیٰ کوبھی جانّ کہتے ہیں.(تاج) فَسَقَ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۳۴.فَسَقَ الرَّجُلُ فِسْقًا:تَرَکَ اَمْرَاللہِ.اللہ کی نافرمانی کی.عَصٰی نافرمان ہو گیا.جَارَعَنْ قَصْدِ السَّبِیْلِ.درست راہ سے روگردان ہو گیا.فَـجَرَ.بدکردار ہو گیا.خَرَجَ عَنْ طَرِیْق الْحَقِّ.حق کی راہ سے الگ ہو گیا.ا َلرُّطْبَۃُ عَنْ قِشْرِھَا: خَرَجَتْ گابھا چھلکے سے باہر آگیا.(اقرب) بدلاً.اَلْبَدَلُ کے معنی ہیں اَلْعِوَضُ.بدلہ.اَلْخَلَفُ.قائمقام (اقرب) تفسیر.تباہی کے ذکر کےساتھ آدم کے واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر جہاں کسی ایسی تباہی کا ذکر ہو.جومامورکی معرفت دنیا پر آئی ہو.وہاں آدم کے واقعہ کا ذکر بھی کیا جاتاہے.اس سے لوگوںکو اس طرف توجہ دلانامقصود ہوتاہے کہ اے لوگو تم سے پہلے آدم کاواقعہ گذر چکا ہے.اس سے فائدہ حاصل کرو.اورشیطان کواپنا دوست نہ بنائو.اس آیت کے ذریعہ گویا لوگوں کوہوشیار کیاگیا ہے کہ مسلمانوںکواوردوسری قوموں کوہوشیار رہناچاہیے کہ پہلے بھی شیطان نے آدم کو گمراہ کرنا چاہا تھا.اوروہ شیطان کے پیچھے چل پڑے تھے.مگر اے آدم کی ذریت تم ہوشیار رہنا اورشیطانی آواز کی اطاعت نہ کرنا.
Page 545
مَاۤ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لَا خَلْقَ میں نے انہیں نہ آسمانوں اورزمین کی پیدائش( کے موقعہ)پرحاضرکیاتھا.اورنہ (خود )ان کی (اپنی )جانوں کی اَنْفُسِهِمْ١۪ وَ مَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا۰۰۵۲ پیدائش کے موقعہ پر اورنہ ہی میں گمراہ کرنے والوںکو(اپنا )مددگاربناسکتاتھا.حلّ لُغَات.عَضُدٌ اَلْعَضُدُ مَابَیْنَ الْمِرْفَقِ اِلَی الْکَتِفِ کہنی سے کندھے تک بازوکے حصہ کو عضد کہتے ہیں.وَیُسْتَعَارُ الْعَضُدُ لِلْمُعِیْنِ.استعارۃً مددگار اورمعاون کو بھی عضد کہتے ہیں (مفردات ) تفسیر.مَاۤ اَشْهَدْتُّهُمْمیں ھُمْ کی ضمیر کا مرجع مَاۤ اَشْهَدْتُّهُمْ کی ضمیر شیطان اوراس کی ذریت کی طرف جاتی ہے اوراس میں یہ بتایاگیا ہےاے لوگوتم شیطان کو کیا اس لئے دوست بناتے ہوکہ اس سے ترقی حاصل کرلو گے.حالانکہ تمہاری پیدائش میں اس کاکوئی دخل نہ تھا.اورنہ اس کاکوئی حصہ زمین و آسمان کی پیدائش میں تھا.بلکہ انسان کی تما م قوتیں نیکی کی خاطرپیداکی گئی تھیں.اوراللہ تعالیٰ گمراہ کرنے والوںکواپنا ساتھی اورخدمت گزار نہیں بناسکتا.پس دنیا میں اگر کوئی قوم جو خدا تعالیٰ سے دور ہو ترقی بھی کرجائے توکبھی یہ نہ خیال کرناچاہیے.کہ اللہ تعالیٰ اب دنیا کاکام اس کے ہاتھ میں دےدے گا.اللہ تعالیٰ تودنیا کی حکومت اپنے ہاتھ میں رکھتاہے اوررکھے گا.ایسے لوگوں کی کامیابیاں تومحض عارضی ہوتی ہیں اورخدا تعالیٰ پھر انسان کو نیکی کی طرف لے جاتاہے.اس آیت پر ذراسا تدبّر کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس میں ایک عظیم الشان مضمون بیان کیاگیاہے گزشتہ مضمون بتارہاہے.کہ شیطان یا اس کی ذریت کو زمین و آسمان کے پیداکرنے میں کوئی دخل حاصل ہونا توالگ رہا ان کو اس سے کوئی دور کاتعلق بھی نہیں ہے.پس صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانہ کااس آیت میں ذکر ہے.اس میں بعض آدم کے مخالف یادین سے بے بہرہ لوگ ایک نئی دنیاکے بسانے کے مدعی ہوں گے اورکہیں گے کہ وہ اپنے زورسے ایک نئی دنیا بسائیں گے.اورایک نیانظام قائم کریں گے.اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتاہے اورفرماتا ہے.کہ کیاکبھی پہلے ایساہواہے کہ نئی دنیا اورنیا نظام بنانے میں اللہ تعالیٰ نے شیطان اورا س کی ذریت سے مدد لی ہو.اگر پہلے کبھی ایسانہیں ہوا.توآئندہ کس طرح ممکن ہے ہمیشہ نئی دنیا اورنیانظام اللہ تعالیٰ آدم اورفرشتوںکے ذریعہ سے
Page 546
بنایاکرتاہے.پس اب بھی اسی طرح ہوگا.نیانظام اورنئی دنیا بھی آدم ہی کے ذریعہ سے بنائے جائیں گے.اور انسان کی تخلیق یعنی بنی نوع انسان کے اندر جو خرابیاں پیداہوجائیںگی.ان کی اصلاح کرکے انسان کو ازسرنو درست کرنے کاکام بھی دنیاوی تدابیر سے نہ ہوسکے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت کے ماتحت ہوگا.قرآن کریم کا یہ کتنا بڑامعجز ہ ہے.تیرہ سوسال پہلے اس نے ان اصطلاحات تک کو بیا ن کردیا ہے جو آخری زمانہ میں استعمال ہونے والی تھی.NEW WORLD اور NEW ORDER کا ذکر کن خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کردیاہے.اورکس طرح اس کابھی جواب دے دیا ہے.کہ آج تک نئی دنیا او رنیانظام آدم کے مخالفوں کے ہاتھ سے خدا تعالیٰ نے تیار نہیں کروایا.بلکہ ہمیشہ آدم اورفرشتوں کے ہاتھ سے کروایا ہے.اسی طرح اب ہوگا.وَ يَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اور(اس دن کوبھی یاد کرو )جس دن و ہ(یعنی خدائے برترمشرکوں کو)کہے گا (کہ اب )تم میرے (ان )شریکو ں فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ کوبلائو جن کے (شریک ہونے کے)متعلق تم دعویٰ کرتے تھے.جس پر وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں (کوئی ) مَّوْبِقًا۰۰۵۳ جواب نہیں دیں گے.اوران کے (او ر ان کے شریکوںکے)درمیان ہم ایک آڑ(حائل)کردیں گے.حلّ لُغَات.موبق.مَوْبِقًا وَبِقَ یَوْبَقُ.کامصدر یااسم ظرف ہے.وَبَقَ کے معنی ہلاک ہونے کے ہیں.مَوْبِقٌ مصدرکے معنی کسی مصیبت میں پھنس کرہلاک ہونے کے ہیں.اوراگرظرف ہوتوا س کے مندرجہ ذیل معنی ہوں گے اَلْمَھْلِکُ.ہلاکت کی جگہ.اَلْمَوْعِدُ.وعدہ کی جگہ.اَلْمَحْبِسُ.قید خانہ.کُلُّ شَیْءٍ حَالَ بَیْنَ شَیْئَیْنِ ہرایسی چیز جودوچیز وں کے درمیان آڑ ہوجائے.وَقِیْلَ مُسَافَۃٌ تَھْلُکُ فِیْھَا الْاَسْوَاطُ لِبُعْدِھَا.بعض نے اس کے معنی دشوا رگزارسفر کے کئے ہیں.(اقرب) تفسیر.یعنی اس وقت اپنے معبودان باطلہ کوبلائیںگے کبھی اپنے اولیاء کو پکاریں گے جن کوشفاعت
Page 547
کاذریعہ خیا ل کرتے ہیں.کبھی حضرت مسیح کوپکار یںگے کبھی ان کی والدہ کو.لیکن ان میں سے کوئی ان کی دعانہ سنے گا.موبق کے مختلف معنی وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا.موبق کے معنی علاوہ اورمعنوں کے پرد ہ اورروک کے بھی ہوتے ہیں.اورہلاکت کے بھی ہیں.پردہ کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے.کہ ان جنگوں میں وہ لوگ ایک دوسرے کاپوراپورابائیکاٹ کریں گے اورہلاکت کے معنوں کے لحاظ سے یہ معنی ہو ں گے کہ ایک دوسرے کوہلاک کریں گے اوراگربَیْنَھُمْ کی ضمیر معبودان باطلہ اورپرستش کرنے والوں کی طرف پھیر ی جائے.تواس میں پہلے مضمون کی تاکید سمجھی جائے گی.یعنی ایسے پردے درمیان میں آجائیں گے کہ ان کی کوئی آواز نہ سنی جائے گی.یایہ کہ ان معبودان کی ارواح ہی ان کے خلاف دعائوں میں لگ جائیں گی.وَ رَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَ لَمْ اورمجرم ا س آگ کودیکھیں گے اورسمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں.اوروہ اس سے (پیچھے )ہٹنے کی يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًاؒ۰۰۵۴ کوئی جگہ نہیں پائیں گے.حلّ لُغَات.مُوَاقِعُوْھَا.وَاقَعَ سے اسم فاعل مُوَاقِعٌ آتاہے.اورمُوَاقِعُوْنَ اس کی جمع ہے.وَقَعَ(وُقُوْعًا)کے معنی ہیں سَقَطَ گرگیا.وَقَعَ فِی الشَّرَکِ جال میں پھنس گیا (اقرب)پس مُوَاقِعُوْھَا کے معنی ہو ں گے اس میں پڑنے والے ہیں.مَصْرفًا: مَصْرِفًایہ صَرَفَ سے اسم ظرف ہے صَرَفَہُ کے معنی ہیں رَدَّہُ عَنْ وَجْھِہِ اس کو اس کے قصد سے پھیر دیا (اقرب)پس مَصْرِفٌ کے معنی ہوں گے پھرنے کی جگہ.تفسیر.نار کے معنی جنگ کے یعنی اس وقت انہیں ہلاکت نظر آئے گی نار کے معنی جنگ کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں آتاہے كُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ (المائدۃ:۶۵)یعنی جب بھی یہود جنگ کی آگ بھڑکائیں گے اللہ تعالیٰ اسے بجھادے گا.ان معنوں کے روسے یہ مطلب ہو گاکہ جنگ کاخطرہ پیدا ہوجائےگا.اورانہیں یقین ہوجائے گا.کہ اب ا س جنگ سے چھٹکارانہیں.اوربہتیری تدبیریں اس جنگ کو روکنے
Page 548
کی کریں گے.لیکن کوئی صورت بھی ا س جنگ سے محفوظ رہنے کی نہ پیداہوسکے گی.ظَنُّوْا بمعنی یقین اس آیت میں ظنُّوْا کالفظ استعمال ہواہے.ا س کے معنی یقین کے ہیں خیال یاشک کے نہیں.ظنّ کا لفظ عربی میں اضداد میں سے ہے.یعنی اس کے معنی گما ن کے بھی ہوتے ہیں اوریقین کے بھی ہیں.وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ١ؕ وَ اورہم نے اس قرآن میں یقیناً ہرایک(ضروری)بات کو مختلف پیرائیوں میں بیان کیا ہے اور(ایساکیوں نہ کرتے كَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۰۰۵۵ کہ)انسان سب سے بڑھ کر بحث کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.الجدل.اَلْجَدَلُ شِدَّۃُ الْخُصُوْمَۃِ سختی سے جھگڑنا (اقرب) تفسیر.اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا کے دومعنی ہیں (۱)اَکْثَرَ شَیْءٍ یَتَأَتّٰی مِنْہُ الْجَدَ لُ یعنی سمجھانے کی جوتدبیر بھی کی جائے اس کے نتیجہ میں اس کی طرف سے جھگڑے کاپہلو ہی پیداکرلیا جاتاہے.اطمینان حاصل کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتا.(۲) جَدَلُ الْاِنْسَانِ اَکْثَرُ مِنْ کُلِّ مَجَادِلٍ(روح المعانی زیر آیت ھذا).یعنی انسان سب مخلوق کی نسبت زیادہ جھگڑا کرتاہے مطلب یہ کہ اسے توہم نے عقل اس لئے دی تھی.کہ روحانی ترقیات کرے.اور خدا تعالیٰ کاعرفان حاصل کرے.مگر وہ اس قوت کوجواسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے.ایک بڑے امتیاز کاذریعہ بنالیتا ہے اوربجائے اس کے کہ اس کے ذریعہ سے دوسرے حیوانوں سے افضل بنے.وہ ان سے بھی ادنیٰ حالت میں چلاجاتاہے.اس آیت میں الناس تما م انسانوں کے متعلق ہے.اورالانسان ان انسانوں کے متعلق جن کااوپر ذکرآچکا ہے اورمطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم میں تمام مسائل کو اچھی طرح سے اورمختلف پیرائوں میں بیان کیا ہے کہ بنی نوع انسان اس سے فائدہ اٹھائیں.مگروہ قسم انسانوں کی جن کا ذکر اوپر گذراہے.اسے جھگڑنے کاذریعہ بنالیتی ہے.اوران ہی تفصیلات کو جو ان کے فائدہ کے لئے ہیں.اعتراض کاموجب سمجھ لیتی ہے.اس میں اس طر ف اشارہ ہے کہ مسیحی لوگ شریعت کی تفصیلات کو لعنت قرار دے کر ان سے آزاد ہوناچاہتے ہیں.حالانکہ وہ تفصیلات انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لئے بیان کی گئی ہیں.
Page 549
وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَ اوران لوگوںکو جب ان کے پاس ہدایت آئی تو(اس پر)ایما ن لانے اوراپنے رب سے يَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ بخشش چاہنے سے صرف اس بات نے روکاکہ پہلے لوگوں کی سی حالت ان پر (بھی)آئے.يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۰۰۵۶ یاپھر عذاب ان کے سامنے آکھڑاہو.حلّ لُغَات.السُّنَّۃُ اَلسُّنَّۃُکے لئے دیکھو حجر آیت نمبر ۱۴.اَلسُّنَّۃُ.اَلسِّیْرَۃُ سنت کے معنی ہیں دستور.اَلطَّرِیْقَۃُ.طریقہ.اَلطَّبِیْعَۃُ.طبیعت عادت.(اقرب) قُبُلاً.اَلْقُبُلُ: نَقِیْضُ الدُّبْرِ.سامنے کاحصہ(اقرب) تفسیر.یعنی قرآن کریم میں ہدایت کاایساسامان موجود ہے کہ اس کے بعد ہدایت میں کوئی روک نہیں ہونی چاہیے تھی.اورچاہیے تھا کہ اس کے مضامین کو سن کریہ لوگ اپنے غلط عقائدسے تائب ہوتے لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے.گویا یہ فیصلہ کرچکے ہیں کہ ہم توضرور عذاب ہی لیں گے.سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اس سے مراد آخری ہلاکت ہے اور اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا سے مراد درمیانی عذا ب ہیں یعنی دونوں قسم کے عذابوںکو یہ بلارہاہے.وَ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ١ۚ وَ اورہم رسولوں کوصرف بشارت دینے والا اور(عذاب کی آمد سے )آگا ہ کرنے والابناکربھیجتے ہیں.اورجن لوگوں يُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَ نے انکار کیا ہے.و ہ جھوٹ کے ذریعہ سے اس لئے جھگڑتے ہیں.کہ اس کے ذریعہ سے حق کومٹادیں.اورانہوں
Page 550
اتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ وَ مَاۤ اُنْذِرُوْا هُزُوًا۰۰۵۷ نے میرے نشانوں کو اور(میرے )انذارکو ہنسی کا نشانہ بنالیاہے.حلّ لُغَات.اَلْبَاطِلُ اَلْبَاطِلُ کے لئے دیکھو نحل آیت نمبر۷۳.لِیُدْحِضُوْابہِ لِیُدْحِضُوا بِہِ أَدْحَضَ سے مضارع جمع مذکر غائب کاصیغہ ہے اوراَدْحَضَ الْقَدَمَ کے معنی ہیں اَزْلَقَہَا پائوں کو پھسلا دیا.اَدْحَضَ الْحُجَّۃُ: اَبْطَلَھَاوَاَزَالَھَا وَدَفَعَھَا دلیل کو پوری طرح رد کیا دورکیا مٹایا (اقرب)پس لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ کے معنی ہوں گے.کہ وہ حق کومٹادیں.دورکردیں.تفسیر.لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ کے معنی یہ ہوئے کہ کافرلوگ باطل کو لے کر جھگڑااوربحث کرتے ہیں.تاکہ اس کے ساتھ حق کو دنیاسے نکال دیں ،باطل کردیں.وَ اتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ وَ مَاۤ اُنْذِرُوْا هُزُوًا.یعنی ہم نشانات تودکھاتے ہیں لیکن یہ ہنسی کرتے ہیں.اس وقت یورپ والوں کی یہی حالت ہے.نشانات کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں.بلکہ ان امور کو بیوقوفوں کے توہما ت سمجھتے ہیں.اورعقلی ڈھکونسلوں کی طرف توجاتے ہیں.مگرخدائی نشانوں کو حقیر سمجھتے ہیں.وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَ اوراس شخص سے زیاد ہ ظالم کون (ہوسکتا)ہے.جسے اس کے رب کے نشانوں کے ذریعہ سے سمجھایاگیا.(لیکن ) نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ١ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ پھر( بھی) وہ ان سے روگردان ہوگیا.اورجوکچھ اس کے ہاتھوں نے (کماکر )آگے بھیجا تھا.اسے اس نے بھلادیا يَّفْقَهُوْهُ وَ فِيْۤ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا١ؕ وَ اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى ان(لوگوں )کے دلوں پر ہم نے یقیناً کئی پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں اوران کے کانوں میں گرانی
Page 551
فَلَنْ يَّهْتَدُوْۤا اِذًا اَبَدًا۰۰۵۸ (پیداکردی ہے)اوراگرتوانہیں ہدایت کی طرف بلائے تو(وہ تجھ سے اس قدر حسد رکھتے ہیں کہ)اس صورت میں وہ ہدایت کو(بھی)کبھی قبول نہیں کریں گے.تفسیر.فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم اورکون ہو سکتا ہے جسے ا س کے رب کی باتیں سنائی جائیں تووہ ان کوحقیر سمجھے اوران سے اعراض کرے اوراس بات کونہ سوچے کہ میں نے خود اپنی عقل سے جوکام کئے ہیں.وہ کس طرح فساد فتنہ اورجنگ کے موجبات بن رہے ہیں.پس باوجود اس تجربہ کے کہ وہ اپنی عقل سے امن پیدا نہیں کرسکا.پھر بھی خدائی امداد اورہدایت کی طرف اس کاتوجہ نہ کرناگویااپنے تجربہ کوٹھکرادینے کے مترادف ہے پھر وہ قوم جوتجربوں پر اپنے کاموں کی بنیا د رکھنے کی مدعی ہے وہ کس قدرمجرم اورغافل ہوتی ہے کہ جزئی تجربوںکوتوا س قدر قیمت دیتی ہے.مگرساری قوم کے تجربہ اوراس کے نتیجہ سے فائدہ نہیں اٹھاتی.فرماتا ہے اس کانتیجہ اس کے سوااور کیا نکل سکتاتھا.کہ جب انہوں نے سمجھ سے کام لینے سے انکار کردیا ہے توہم بھی ان کوسمجھ سے محروم کردیں.اورانہیں ان کے حال پر چھو ڑدیں کہ خواہ کوئی کتنی ہی انہیں نصیحت کرے یہ فائدہ نہ اٹھاسکیں.وَ رَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ١ؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا اورتیرارب بہت ہی بخشنے والا (اوربہت ہی )رحمت کرنے والا ہے.اگروہ اس کی وجہ سے جوانہوں نے (اپنی جانوں كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ١ؕ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ کے لئے )کمایا ہے.انہیں ہلاک کرناچاہتاتووہ ان پر فوراً عذاب نازل کردیتا.(مگر وہ ایسانہیں کرتا )بلکہ ا ن کے لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِٕلًا۰۰۵۹ لئے ایک میعاد (مقرر)ہے جس سے ورے (یعنی پیشتراس کے کہ عذاب کوبھگتیں)ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے تفسیر.لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ.اگران کو خدا تعالیٰ ان کے اعما ل کی وجہ سے
Page 552
سزادینے لگتا توکبھی کاہلاک کردیتا.مگرخدا تعالیٰ ہوشیار کئے بغیر کسی قوم کوہلاک نہیں کرتا.اس لئے وہ پہلے ان کوہوشیار کرے گا.اورزمانہ کے مامورکے ذریعہ سے حجت پوری کرکے پھر پکڑے گا.بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهٖ مَوْىِٕلًا.ان کے لئے وعدہ مقرر ہے.و ہ ہرگز اس سے ہٹ کرکوئی پنا ہ کی جگہ نہ پائیں گے یعنی خدا تعالیٰ کو چھو ڑ کر اورکوئی بھی نجا ت کی جگہ ان کو نہ مل سکے گی.وَ تِلْكَ الْقُرٰۤى اَهْلَكْنٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ اوروہ (گزشتہ نبیوں کے مخالفوںکی)بستیاں جوہیں تو(ان کاواقعہ یوں ہے کہ)ہم نے اس وقت انہیں ہلاک کیا جب مَّوْعِدًاؒ۰۰۶۰ انہوں نے ظلم کیا.اوران کی ہلاکت کے لئے (بھی )ہم نے ایک معیاد مقرر کردی تھی.(تاو ہ چاہیں توتوبہ کرلیں ) تفسیر.یعنی ہزاروں قومیں گذرچکی ہیں جب انہوں نے ظلم کیا.یعنی اللہ تعالیٰ کے انذار کی قدرنہ کی توہم نے ان کو ہلاک کردیا.اوران کی ہلاکت کی پہلے سے خبر دے دی جس کے مطابق وہ ہلاک ہوگئے.پس اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو خواہ کس قدر ترقیا ت ہی کیوں نہ ملی ہوں.پھر بھی وہ انسان ہیں.پس کوئی وجہ نہیں کہ جب پہلے انسان خدا تعالیٰ سے منہ پھیر کرہلاک ہوئے تویہ ہلاک نہ ہو ں.آجکل قریباً ۹۹فیصدی لوگوں کاخیال ہے کہ اب یورپ تبا ہ نہیں ہوسکتا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بیوقوفی کی بات ہے پہلی بادشاہتوں کے زمانوں میں کو ن کہتاتھا کہ وہ تبا ہ ہوں گی.مسلمانوں کے متعلق کون کہتاتھا کہ ان کی حکومت تبا ہ ہوگی.اسی طرح رومیوں کی حکومت او رایرانیوں کی حکومت کے متعلق بھی کوئی اس وقت گمان نہ کرتاتھا.لیکن ساری تباہ ہوگئیں.اسی طرح ان کی بادشاہت کے تباہ ہونے کے متعلق بھی حیرانی اورتعجب خلاف عقل ہے.وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبْرَحُ اور(تم اس وقت کو بھی یاد کرو)جب موسیٰ نے اپنے نوجوان (رفیق)سے کہا تھا (کہ )میں(جس راستے پرجارہا حَتّٰۤى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ ہوں اس پر قائم رہنے سے )نہیں ٹلوں گایہاں تک کہ ان دونوں سمندروں کے اکٹھے ہونے کے مقام پر پہنچ جائو ں
Page 553
اَمْضِيَ حُقُبًا۰۰۶۱ یاصدیوں تک (آگے ہی آگے) چلتاچلاجائوں.حلّ لُغَات.الفَتٰی اَلْفَتٰیکے معنے نوجوان کے ہیں.اس کی جمع فِتْیَانٌ آتی ہے.مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف آیت نمبر ۶۳.فِتْیَانٌ جَمْعُ فَتٰی کی ہے اس کے معنے جوان کے ہیں لیکن جب کسی کی طرف مضاف ہو تو ا س کے معنے بیٹے یا نوکر کے ہوتے ہیں جیسے فَتٰی زَیْدٍ زید کا بیٹا یا نوکر.لَاابرحلَااَبْرِحُکے لئے دیکھویوسف آیت نمبر ۸۱.مَابَرِحَ فُلَانٌ کَرِیْمًا اَیْ بَقِیَ عَلٰی کَرَمِہِ.اَبْرَحُ بَرِحَ سے مضارع متکلم کا صیغہ ہے اور مَا بَرِحَ فُلَانٌ کَرِیْمًا کے معنے ہیں اپنی سخاوت پر قائم رہا.(اقرب) بَرِحَ وَزَالَ اِقْتَضَیَا مَعْنَی النَّفِیْ وَلَا لِلنَّفِی وَالنَّفْیَانِ یَحْصُلُ مِنْ اِجْتِمَاعِھِمَا اِثْبَاتٌ.بَرِحَاور زَالَ کے اندر نفی کے معنے پائے جاتے ہیں کیونکہ کسی جگہ سے چلے جانے کے مفہوم میں نہ موجود رہنا بھی داخل ہے جو نفی پر مشتمل ہے.پس جب ان پر مَا یا لَا وغیرہ کوئی کلمہ داخل ہوگا تو نفی پر نفی داخل ہونے کی وجہ سے ان میں اثبات کے معنے یعنی کسی جگہ پر موجود رہنے کے معنے پیدا ہوجاتے ہیں.(مفردات) اَمْضِیْ اَمْضِیْ مَضَی سے مضارع متکلم کاصیغہ ہے اورمَضَی الشَّیْءُ(یَمْضِیْ وَیَمْضُوْ) کے معنے ہیں ذَھَبَ وَخَلَا.کوئی چیز گزر گئی اورچلی گئی (اقرب)پس اَمْضِیْ کے معنے ہوں گے کہ میں چلتاچلاجائوں.حُقبًا.حُقُبٌ حُقْبٌ کی جمع ہے.اوراس کے معنے ہیں ثَمَانُوْنَ سَنَۃً.اسّی سال کاعر صہ.وَیُقَالُ اَکْثَرُ مِنْ ذَالِکَاوربعض کہتے ہیں اس سے بھی زائد عرصہ کوحُقُبٌ کہتے ہیں.اَلدَّھْرُ.زمانہ.اَلسَّنَۃُ وَقِیْلَ السُّنُوْنَ مطلق ایک سال کے عرصہ کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اوربعض کہتے ہیں کہ کئی سال کاعرصہ حقب کہلاتاہے.(اقرب) تفسیر.پہلے توتمثیلوں سے اس امر کوبتایاکہ عیسائیت اوراسلام کامقابلہ گوکمزوراورطاقتورکامقابلہ ہے لیکن غورکیا جائے توطاقتوروہ ہے جوخدا تعالیٰ کی طر ف توجہ کرتاہے ،وہ نہیں جو دنیا کے کاموں میں مشغول ہے.اوراشارۃً یہ بھی بتایا کہ مسیحیت کی ترقی اس رنگ میں مقد رتھی کہ پہلے ایک دفعہ یہ قوم ترقی کرے.پھررسول کریم
Page 554
صلی اللہ علیہ وسلم کاظہورہو.اور کچھ عرصہ اسلام ترقی کرے.پھر دوبارہ انہیں ترقی ملے.اب اس مضمون کوآسمانی کتب کے حوالہ سے ثابت فرماتا ہے.یادرکھنا چاہیے کہ جیساکہ میں پہلے بتاآیا ہوں اسلام کے دشمنوں کایہ اعتراض ہے کہ اس سورۃ میں بغیر تعلق کے واقعات جمع کردیئے گئے ہیںاورخود مسلمانوں کے لئے بھی ان واقعات کا اجتماع حیرانی پیداکرنے کاموجب بنا رہاہے.اورانہوں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کوتسلی دی ہے کہ یہود نے کچھ سوالات کئے تھے ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے اکٹھاکرکے دےدیاہے.لیکن جیساکہ ظاہر ہے یہ بات نہیں.کیونکہ اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اگر کوئی سوال تھا بھی تو ان دونوں واقعات کے درمیان میں اوپر کی تمثیلات اورپھر حضرت موسیٰ کے اس واقعہ کو جواس رکوع میں بیان ہواہے کیوں رکھ دیاگیاہے.کم سے کم ان دونوں سوالوں کے جواب اکٹھے رکھے جاتے.اصل بات یہ ہے کہ یہ سب مضامین ترتیب سے بیان ہوئے ہیں.اورہرواقعہ اور تمثیل کو خاص ضرورت سے اپنے اپنے مقام پر رکھا گیا ہے.چنانچہ اصحاب کہف کے ذکر کے بعد ان تمثیلات کے رکھنے کی حکمت تومیں بتاآیاہوں.اب میں حضرت موسیٰ کے اس واقعہ کو اس جگہ رکھنے کی وجہ بتاتاہوں.میں ذکر کرچکاہوں کہ عیسائیوں کی قومی زندگی میں ایک عجیب بات پائی جاتی ہے جس کی کوئی اورمثال کم سے کم مجھے معلوم نہیں.اور وہ یہ کہ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ایک ترقی کادور ملا.درمیان میں ا یک اورنبی پیداہوااوراس کی قوم کو ترقی کاایک دورملا.اس کے بعد پھر مسیحی قوم کی ترقی شروع ہوگئی.ا س واقعہ کی طرف پہلے تمثیل میں نہر کے لفظ سے اشار ہ کیاگیاتھا.اب حضرت موسیٰ کے واقعہ کو اس جگہ رکھ کر اس مضمون کوواضح کیاگیاہے اوروہ اس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ؑ تھے.جیساکہ استثناء باب ۱۸آیت ۱۸ میں پیشگوئی کی گئی تھی.کہ’’میں ان کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپاکروں گا.اوراپناکلام اس کے منہ میں ڈالوں گا.اورجو کچھ میں اُسے حکم دو ںگاوہی وہ ان سے کہے گا‘‘.آنحضرت ؐ کی مشابہت حضرت موسیٰ ؑسے قرآن کریم میں بھی اس پیشگوئی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیاگیاہے کہ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (المزمل :۱۶)سوحضرت موسیٰ کے واقعہ کو مسیحیوں کی ترقی کے دونوں دوروں کے درمیان میں بیان کرکے اس طرف اشارہ کیا گیاہے کہ مثیل موسیٰ ان دونوں دوروں کے درمیان میں پیداہوناضروری تھا.تااس شبہ کاازالہ کیاجائے کہ اگرمسیحی ترقی کے پہلے دور کے بعد ایک سچانبی آیا تھا توکیوں مسیحی ترقی کادور ختم نہیں ہوگیا.پس اس دور کاپھر پہلے سے بھی زیادہ زورسے شرو ع
Page 555
ہوجانابتاتاہے کہ درمیانی نبی سچانہ تھا.ورنہ وہ ان کی ترقیات کوروک دیتا.یہ بات ذوقی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کاجوواقعہ آگے بیان ہواہے.اس کامضمون بھی ا سی کی تصدیق کرتاہے.جس کی تشریح اگلی آیات میں کی جائے گی.سردست میں نے اس طرف اشارہ کردیاہے کہ چونکہ مسیحی ترقی کے پہلے دور اور دوسرے دور کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاظہور مقد رتھا.اس لئے مسیحی ترقی کے دونوں دوروں میں فاصلہ رکھا گیاہے.اوردرمیان میںحضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کردیاگیاہے.جن کے مثیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے.تاجس طرح واقعات نے ظاہر ہوناتھا اسی طرح ان کا ذکر کیاجائے.یہ واقعہ جو اس رکوع میں بیان ہواہے.اس کے بارہ میں مفسرین میں اختلاف ہے مفسرین اکثر اس طرف گئے ہیں اوربعض احادیث میں بھی ا س کا ذکر آتاہے کہ خضرنامی ایک شخص سے ملاقات کے لئے حضرت موسیٰ ؑ تشریف لے گئے تھے.ان آیات میں ا س سفرکے حالات بیان کئے گئے ہیں.یہ سفرانہوں نے کیوں کیاتھا اس کے متعلق بھی اختلاف ہے.بعض نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے خدا تعالیٰ سے پوچھاکہ کیامجھ سے زیاد ہ علم والابھی کوئی شخص ہے.تواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایک شخص ہے.اورپھر اس شخص کاپتہ بتایا.جس پرحضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کو ملنے کے لئے گئے.ایک روایت میں یہ آتاہے کہ بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی اورعالم ہے.توانہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں.اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اوراس شخص کاپتہ دیا ، جوان سے بڑھ کرعالم تھا.اورا س پروہ اس سے ملنے کے لئے گئے (بخاری کتاب التفسیر سورۃ الکہف،کشاف ، قرطبی ابن جریر زیر آیت ھذا).ان پیشگوئیوں کی تفصیل جو سورہ کہف کے واقعات میں مضمر ہیں درحقیقت اس واقعہ کے سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی ہے.بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کاواقعہ سورئہ بنی اسرائیل میں بیان کیاگیاتھا اوراس اسراء کے نتائج بیان کئے گئے تھے کہ آئندہ کیاکیا واقعات ظاہر ہوں گے اورمسلمانوںکو کس طرح ترقیات ملیں گی.پھر اسراء کی بیان کر دہ کامیابیوں میں مسلمانوں کے لئے جوخطرات پیش آنے والے تھے ان کا ذکرکیاتھا.یعنی یہود اورنصاریٰ کی مخالفتوں کا ذکر کیاگیاتھا.ان عظیم الشان خطرات میں سے ایک بڑاخطرہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی امت کاایک گروہ جوعیسائی کہلاتے ہیں (اگرچہ وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کی امت نہ کہیں مگر خداکے نزدیک وہ حضر ت موسیٰ ہی کی امت میں شامل ہیں )مسلمانوں کوآخری زمانہ میں سخت صدمہ پہنچانے والاتھا.اس لئے اللہ تعالیٰ
Page 556
نے اس کی تشریح کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے علاوہ خود حضرت موسیٰ کے اسراء کوبھی اس جگہ بیان فرمایا ہے.جس سے ا س امر کی تصدیق مطلوب ہے کہ آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے اورآپ ؐ کی امت کو غلبہ دیاجائے گا.اورموسوی امت کابقیہ حصہ (عیسائی لوگ )غالب نہ ہوسکے گا.یہ واقعہ حضر ت موسیٰ ؑ کاایک کشف ہے میرے نزدیک ظاہرجسم کے ساتھ ایساکوئی واقعہ انہیں پیش نہیں آیا.استاذی المکرم حضرت مولوی نورالدین صاحبؓ کی یہی رائے تھی(حقائق الفرقان سورۃ الکہف زیر آیت واما الغلام...).اورمیں اس بارے میں غور کرکے اسی نتیجہ پر پہنچاہوں کہ ان کی یہ رائے درست تھی.اور میرے نزدیک بھی یہ کشف ہی ہے جس کے ثبوت مَیں ذیل میں بیان کرتاہوں.حضرت موسیٰ کے سفر کے کشف ہونے کے ثبوت (۱)پہلاثبوت ا س کایہ ہے کہ اس قسم کے کسی سفرکے واقعہ کا ذکر بائیبل میں موجودنہیں.جس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ واقعہ ظاہر ی طورپر ظہور میں نہیں آیا.یہ تو ہوسکتا ہے کہ اس کے طرز بیان میں کچھ اختلاف ہوجائے مگرسرے سے ہی اس واقعہ کانہ پایاجاناایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے.بنی اسرائیل کی روایات سے معلوم ہوتاہے کہ حضرت موسیٰ کوبھی معرا ج ہواتھا(جیوش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Ascesion) (چنانچہ مجھے معلوم ہواہے کہ عزیزم مولوی جلال الدین شمس صاحب نے یہودی روایات لندن میوزیم کی کتب دیکھ کرنکالی ہیں جن میں اس واقعہ کا ذکرہے.اوریہودی کتب میں اس سفرکو جسمانی سفرقرار دیاہے.مگر ان کا یہ لکھنا ہم پر حجت نہیں.مسلمانوں سے بعض نے بھی تواسراء کو بلکہ معراج کو جسمانی قرا دےدیاہے ) (۲)بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے سے پہلے حضر ت موسیٰ کاایک ہی سفرثابت ہے جومدین کی طرف ہوا.قرآن کریم میں بھی متعد د بار اس کا ذکر آیاہے.اورقرآن اوربائیبل دونوں اس با ت پرمتفق ہیں کہ اس سفر میں وہ اکیلے تھے.لیکن زیربحث واقعہ میں ان کے ساتھ ایک ساتھی کابھی ذکر ہے.جوان کے ماتحت معلوم ہوتاہے کیونکہ فَتٰی کے لفظ کو جب مضاف بناکراستعمال کیاجائے.اس کے معنی بیٹے کے یاماتحت کے ہوتے ہیں.پس سفر مدین پر یہ الفاظ چسپاں نہیں ہوسکتے.اوراس کے سوااورکوئی سفر ان کابائیبل سے ثابت نہیں.لہٰذااسے کشف ہی مانناپڑے گا.(۳)بعثت کے بعد بھی حضرت موسیٰ کاکوئی ایساسفر ثابت نہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے علیحدہ ہوکر کیاہو.بائیبل میں شروع سے لے کر آخیر تک ان کے واقعات ترتیب کے ساتھ موجود ہیں.لیکن اس سفرکاکہیں ذکر نہیں
Page 557
جس سے معلوم ہوتاہے کہ یہ سفرکوئی مادی واقعہ نہ تھا.(۴ )حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے چالیس دن کےلئے چند میل دورپہاڑ پر خدا کاکلام سننے کے لئے گئے تواتنے ہی دنوں میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنالیا.جب چالیس دن کی غیرحاضری نے یہ تباہی مچادی تھی تواتنے لمبے سفر کی صورت میںکیانتیجہ ہواہوگا.مگراس موقعہ پر بنی اسرائیل کے اندر کوئی فساد نہیں ہوا.کیونکہ بائیبل میں اس فساد کے علاوہ اور کسی فساد کا ذکرنہیں.نیز اس فساد کے بعد یہ دانشمندی کے خلاف ہوتاکہ آپ اتنالمباسفر کرتے.(۵)چالیس دن کے سفر پرجاتے ہوئے حضرت موسیٰ ؑ اپنے بعد حضر ت ہارون کو خلیفہ مقررکرکے جاتے ہیںمگراس ایک دفعہ کے واقعہ کے بعد کہیں بھی ثابت نہیں کہ حضرت موسیٰ ؑ نے حضرت ہارون یاکسی اورکو اپناخلیفہ مقرر کیاہو.اگر سفر کا ذکر نہیں تھا توکم از کم اس نیابت کا ذکرتوضرور تورات میں ہوناچاہیے تھا.مگرچونکہ ایساکوئی ذکر بائیبل میں نہیں ہے.تویہی مانناپڑتا ہےکہ ایساکوئی جسمانی سفرواقعہ نہیں ہوا.کیونکہ یہ توہرگزتسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ حضر ت موسیٰ ؑ سفر پرگئے ہوں اوراپنا جانشین مقررنہ کرگئے ہو ں.(۶)یہ امر انبیاء کی سنت کے خلاف معلوم ہوتاہے کہ نبوت کے بعد وہ اپنی قوم سے ایک لمبے عرصہ کے لئے الگ ہوئے ہو ں.جن انبیاء کاتاریخ سے ہمیں پتہ چلتاہے ان میں سے ایک کی سوانح میں بھی اس امر کاپتہ نہیں چلتا.بے شک ہمارے عقیدہ کی روسے حضرت مسیح اپنی قوم سے الگ ہوئے.مگروہ درحقیقت ایک حصہءِ قوم سے جداہوکر دوسرے حصہ کی طرف گئے تھے.اوراس کی مثالیں بکثر ت انبیاء میں پائی جاتی ہیں.کہ انہوں نے اپنی قوم کے اند رتبلیغی سفرکئے ہیں.مگرحضرت موسیٰ کایہ سفرتبلیغی نہیں.نہ اپنی قوم کے علاقہ میں ہے.بلکہ وہ صرف یہ معلوم کرنے کے لئے اپنی امت کوچھوڑ کرچلے جاتے ہیں کہ ایک شخص مجھ سے بھی زیادہ عالم ہے.(۷)حضرت ابن عباسؓ نے اسی واقعہ کے اند ر جوکنز کا ذکر ہے اس کی تعبیر میںفرمایا ہے.مَاکَانَ الْکَنْزُ اِلَّاعِلْمًا(ابن کثیر سورۃ الکہف قولہ تعالیٰ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا)یعنی اس واقعہ میں جو کنز کا ذکر ہے.اس سے علم کے سوااور کچھ مراد نہیں.ظاہر ہے کہ یہ تعبیر ہے اورتعبیرکشف ہی کی ہوسکتی ہے.اگروہ کنز علم تھا تویہ بھی ظاہر ہے کہ وہ دیوار جو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی نے بنائی وہ بھی ماد ی دیوار نہ تھی.اورکھا ناطلب کر نے کاواقعہ بھی مادی نہ تھا.اورجب یہ حصہ کشف تھا توظاہر ہے کہ ساراواقعہ ہی کشف تھا.اس واقعہ کے کشف ہونے کاثبوت اندرونی شہادتوں سے (۸) واقعہ کی اندرونی شہادت بھی یہی
Page 558
ثابت کرتی ہے کہ یہ کوئی جسمانی واقعہ نہیں.مثلاً خرق سفینہ کے واقعہ کو لے لو.اس میں جولکھا ہے کہ انہوں نے کشتی میں بڑاسوراخ کردیا.تاکہ بادشاہ اس کوچھین نہ لے.اس پر سوا ل یہ ہے کہ کیااس شگاف سے وہ کشتی بے کار ہوگئی تھی ؟اگرکہا جائے کہ نہیں.توا س پر سوال پیدا ہوتاہے کہ پھر بادشاہ نے اس کوکیوں نہ چھینا جبکہ وہ ابھی کارآمد تھی.اوراگرکہو کہ بالکل نکمی ہوگئی تھی.توپھر سوال ہوتاہے کہ اس سوراخ کی وجہ سے و ہ دریامیں غرق کیوں نہ ہوگئی.ظاہر ی طورپر کوئی ایسی کشتی جس کاتختہ نکال کر اس کو بالکل بیکا رکردیاگیاہو غرق ہونے سے بچ نہیں سکتی تھی.ہاں کشف میں یہ نظارہ دیکھنا خلاف عقل نہیں ہوتا کہ کوئی تختہ بھی نکال دیاجائے اورکشتی غرق بھی نہ ہو.پھرقتل نفس کاواقعہ ہے.یہ بھی ظاہری واقعہ نہیں ماناجاسکتا.کیونکہ حضرت موسیٰ کو سبق سکھانے والایاکوئی نبی ہوگا یاکوئی بڑابزرگ.لیکن قتل نفس بغیر نفس توکوئی ادنیٰ مومن بھی نہیں کرسکتا.کجایہ کہ ایک عظیم الشان نبی ایسے فعل کاارتکاب کرے.اس کے جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے چونکہ آئند ہ قتل کرنے تھے.اس لئے اس کوقتل کردیا.مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہے اورخلاف شریعت.اگر ارتکاب جرم سے پہلے محض علم کی بناء پر سزادیناجائز ہے توپھر خدا تعالیٰ کو سب لوگوں کے گناہوں کا قبل از وقت علم ہے وہ کیوں سب کوسزانہیں دیتا.شریعت کااصولی قانون یہی ہے کہ جب تک کوئی کسی گناہ کامرتکب نہ ہوجائے ،اس کوسزانہیں دی جاسکتی.اس اصل پر شرائع کااختلاف اثرانداز نہیںہوسکتا.یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ عملاً قتل کیا کرتا تھا.مگراس کاپتہ نہ لگتاتھا (تفسیر مظہری سورۃ الکہف زیر آیت حتی اذا لقیا...).یہ جواب بھی نہایت بوداہے.اگریہ بات صحیح ہے.توقرآن مجید کوچاہیے تھا کہ یہ وجہ بتاتا.تاکہ لوگوں کی تسلی ہوجاتی.اورانہیں معلوم ہوجاتاکہ بلاوجہ اس نوجوان کو قتل نہیں کیا گیا.آخری واقعہ دیوار کاہے.اس کوبھی ظاہری حالت میں تسلیم نہیں کیاجاسکتا.بھلایہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھی کے دیوار بنادینے پر حضرت موسیٰ ؑ جیسا وسیع الحوصلہ او رعظیم الشان نبی اس لئے اعتراض کرے کہ شہر کے لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا.شہر والوں کے کھانانہ کھلانے کاالزام ان پر تھا نہ کہ ان دو بیکس یتیموں پر جن کی وہ دیوار تھی.اوریو ں بھی یہ بات حضرت موسیٰ ؑ کی شرافت نفس سے بہت بعید ہے کہ و ہ دویتیموں کی دیوار پر اجر نہ لینے پر اعتراض کریں.غرض واقعہ کی اندرونی شہاد ت بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ ایک کشف ہے نہ کوئی ظاہر ی واقعہ.(۱۰)یہ ساراواقعہ بحیثیت مجموعی بھی ثابت کرتاہے کہ یہ ایک کشف تھا.کیونکہ جو تین باتیں اس سفرمیں بتائی
Page 559
گئی ہیں.اگرو ہ ظاہر ی لی جائیں تووہ ایسی نہیں ہیں کہ ان کے لئے کوئی معمولی مومن بھی سفرکرے کجا یہ کہ حضرت موسیٰ ؑ کو ان باتوں کے سیکھنے کے لئے بھیجاجائے.کیاحضرت موسیٰ ؑ یہ سیکھنے گئے تھے.کہ کشتی کاتختہ کیسے توڑا جاتاہے یاقتل کیونکر کیا جاتاہے یادیوار کےبنانے کی کیاترکیب ہے یااس پر اجر لیناچاہیے یانہیں.ان باتوں کے سیکھنے کے لئے تو ایک جاہل گنواربھی سفر نہیں کرے گا.غرض ان باتوںمیں سے کوئی بھی تو ایسی بات نہیں کہ جس کو ظاہرصورت میں مان کر حضرت موسیٰ ؑ جیسے اولوالعز م اورذی شان نبی کاسفرجائزاورمعقول قرار دیاجاسکے.(۱۱)ماوردی نے روایت کی ہے کہ جس شخص کے پاس حضرت موسیٰ ؑ گئے تھے وہ ایک فرشتہ تھا (ابن کثیر) پس یہ واقعہ کشف ہی ماننا پڑے گاورنہ ظاہر ی سفر کرکے فرشتے کے پاس جانے کے کیا معنے ہوں گے.فرشتہ توپل مارنے میں خود ان کے پاس آسکتاتھا.(۱۲)آنحضر ت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ’’وَدَدْنَا اَنَّ مُوْسٰی کَانَ صَبَرَ حَتّٰی یَقُصَّ اللہُ عَلَیْنَا مِنْ خَبَرِھِمَا (بخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالیٰ و اذ قال موسیٰ لفتہ)کاش موسیٰ ؑ صبرکرتے اورخاموش رہتے تاکہ خدا تعالیٰ ہمیں ان کی اورخبریں بھی بتادیتا.اگرا س واقعہ کو ظاہر ی واقعہ سمجھاجائے توآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توبہت ارفع ہے میں بھی اپنے ذہن میں ان امورکے معلوم کرنے کاکوئی شوق نہیں پاتااورنہ ہی میرے نزدیک کوئی سمجھدار انسان ایسی سطحی باتوں کے متعلق زیادتی علم کی خواہش کرسکتاہے.پس معلوم ہواکہ یہ آئندہ کی اخبار تھیں جوکشفی رنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام پرظاہر ہوئیں اور چونکہ وہ غیب پرمشتمل تھیں اورآئندہ امت محمدیہؐ کے حالات کوظاہرکرتی تھیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش تھی کہ کاش موسیٰ ؑ خاموش رہتے اوراوربھی باتیں کھل جاتیں.ان دلائل سے ثابت ہے کہ یہ واقعہ کشف کاواقعہ ہے.اگرچہ مصدقہ بائیبل کاکوئی حوالہ ہمیں نہیں ملتا جس میں اس واقعہ کاکسی رنگ میں بھی ذکر ہو.مگر یہود کی روایات کی کتب میں ایسی رویات موجود ہیں اورمسلمانوں کی روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں بھی یہود میں ضروراس قسم کی روایات پائی جاتی تھیں ورنہ مسلمان انہیں کہاں سے لے سکتے تھے.مگر یہود کی روایات کاہمار ی تحقیق پر کوئی اثر نہیں ہوسکتا.جب تک قرآن کریم عقل اورمشاہد ہ ان کی تصدیق نہ کرے.ہم ان کوماننے پر مجبور نہیں.بلکہ بغیر ان قیود کے ان کاماننا خطرہ سے خالی نہیں.خلاصہ یہ کہ عقل ونقل اس واقعہ کو ایک کشف قرار دیتے ہیں.
Page 560
حضرت خلیفہ اولؓ کے نزدیک عبد سے مراد آنحضرت ؐ تھے وہ شخص جس سے حضرت موسیٰ ؑ اسراء میں سبق لینے گئے تھے.اس کے متعلق استاذی المکر م حضرت مولوی نورالدین صاحب ؓ کی رائے تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاوجود متمثل ہواتھا.میں نے جب اس پرغورکیا.تومیں بھی اس یقین پر پہنچا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت موسیٰ ؑ کو متمثل ہوکر نظر آئے تھے.اوریہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ کاش موسیٰ خامو ش رہتے.توہمیں اورحالات بھی معلوم ہوجاتے.یعنی ہمیں پتہ لگ جاتاکہ ہمارے ساتھ کیا واقعات پیش آنے ہیں.آنحضرت ؐ کے زمانہ کے حالات حضرت موسیٰ ؑ پر کشفی طور پر ظاہر ہوئے میرااپنا یہ خیال ہے.گویہ خیال ایک ذوقی نظریہ ہے کہ جس وقت کوہ سیناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت موسیٰ ؑ کو بشارت دی گئی (دیکھو استثناء باب ۱۸آیت ۱۸)اورانہیں معلوم ہواکہ ایک عظیم الشان نبی میرے بعد پیدا ہونے والا ہے.توان کے دل میں یہ معلوم کرنے کی خواہش پیداہو ئی.کہ وہ کونسی تجلّی ہوگی جواس نبی پر ظاہر کی جائےگی.جس پرانہوں نے عرض کیا.’’رَبِّ اَرِنِيْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ.‘‘ذرامجھ پر بھی وہ محمدی تجلّی ظاہر فرما.تاکہ میں بھی تودیکھو ں.کہ اس پر توکس شان سے ظاہر ہوگا.اس کاانہیں یہ جواب دیاگیا.کہ ایسانہیں ہوسکتا.ہرشخص اپنے مناسب حال ہی تجلی دیکھ سکتاہے.میرے اس بیان کی تائیداس سے بھی ہوجاتی ہے کہ حضرت موسیٰ ؑ اس سے پیشتر روحانی تجلی دیکھ چکے تھے.جیساکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ’’اِنِّيْۤ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ١ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ‘‘(طہ:۱۳).پھر جبکہ و ہ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھ چکے تھے توان کے اس قول کے کیامعنے ہوئے کہ اے اللہ مجھے اپناآپ دکھا.اگراس کے یہ معنے کئے جائیں کہ پہلے روحا نی تجلی دیکھی تھی اب وہ اللہ تعالیٰ کواس کی اصل صورت میں دیکھناچاہتے تھے.تواس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی کوبیوقوف قرار دیاجائے.نعوذ باللہ من ذالک.کیونکہ کسی کایہ کہنا کہ اے خداتومجھے مجسم ہوکرنظرآ.نادانی کی بات ہے.اوریہ بات حضرت موسیٰ کی طرف ہر گز منسوب نہیں ہوسکتی.پس یہ رؤیت کی درخواست روحانی ہی قرار دی جاسکتی ہے.اور چونکہ موسوی تجلی پہلے ان پر ہوچکی تھی.اس سے معلوم ہوتاہے کہ اب جو خواہش انہوں نے کی توو ہ کسی اوررؤیت کے لئے تھی.اور چونکہ اس درخواست سے معاً پہلے انہیں محمدرسول اللہ صلعم کی بشار ت دی گئی تھی.حضرت موسیٰ ؑ خدا تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکے جو آنحضرت ؐ پر ہوئی تھی مَیں یہی قیاس کرتاہوں.کہ یہ درخواست ان کی محمدی تجلی کے دیکھنے کے بارہ میں تھی.جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ
Page 561
’’لَنْ تَرَانِیْ‘‘کہ تومجھے اس صورت میں نہیں دیکھ سکتا.جس صورت میں کہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا ہے.کیونکہ اس کے دیکھنے کے لئے محمدی مرتبہ کی ضرورت ہے.جوتجھے حاصل نہیں.یہی وجہ تھی کہ ’’لَنْ تَرَانِیْ ‘‘کہہ کر پھر اللہ تعالیٰ نے جلوہ دکھایا.چنانچہ موسیٰ نے دیکھ لیا کہ واقعہ میں وہ اس جلوہ کے مطابق ظرف نہ رکھتے تھے.اس وجہ سے وہ اس جلوہ کودیکھتے ہی بےہوش ہوگئے.میں سمجھتاہوں کہ حضر ت موسیٰ علیہ السلام کو رسول کریم صلعم کی شان اعلیٰ کے دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کشف دکھایا اوراس کشف کاخضر میرامحمدؐہی ہے جس کے ساتھ چلنے کی موسیٰ علیہ السلام کوطاقت نہ تھی.اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَعَلیٰ اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مُجِیْدٌ.حضرت موسیٰ ؑ کے ساتھ کا جو ان حضرت عیسیٰ ؑ تھے وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ.فتی کے متعلق روایات میں لکھا کے کہ وہ یوشع بن نون تھے (کشاف زیر آیت ھذا).کوئی تعجب نہیں کہ کشف میںحضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کوہی ساتھ دیکھا ہو.لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ دوسراشخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے.جنہوں نے موسوی سلسلہ کے سفرکے آخری دور میں قوم کی راہنمائی کرنی تھی.اورگویا موسوی سفر کااختتام ان کی معیت میں ہونا تھا.اس کاثبوت میرے نزدیک اس آیت سے بھی ملتاہے کیونکہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گھر سے ایک نوجون کو لے کرچلے.بلکہ خود ان کے چلنے کابھی ذکر نہیں.ذکر ہے تویہ کہ موسیٰ نے اپنے آپ کوسفر کی حالت میں دیکھا اوراس وقت ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا.انہو ں نے اس نوجوان سے کہا کہ جب تک میں مجمع البحرین تک نہ پہونچ جائو ں میں اپناسفرختم نہ کروں گا.خواہ مجھے صدیوں تک ہی کیوں نہ سفرکرنا پڑے.زمانہ کے لئے جولفظ اس آیت میں استعمال ہواہے.وہ حُقُب کاہے.اوریہ لفظ حُقْبٌ کی جمع ہے.حُقْب کے معنے اسّی سال یااس سے زیادہ سالوں کے ہوتے ہیں.درحقیقت یہ لفظ عربی میں صدی کاقائمقام ہے.پس حُقُبٌ جو جمع ہے.اس کے معنے ہوئے صدیاں.مگر بعض دفعہ اس لفظ کو ایک سال یاکئی سال کے لئے بھی استعمال کرلیتے ہیں.اگر یہی معنے لئے جائیں توبھی آیت کے معنے یہ ہوں گے کہ سالوں چلتاجائوں گا.یایہ کہ دسیوں سال چلتاچلاجائوں گا.ظاہر ہے کہ ایک نبی کاامت سے سالہا سال تک جدارہنا عقل کے خلاف ہے.بلکہ خود نبوت کی ضرورت کو مشتبہ کر دیتاہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی.توآپؐ نے مکہ سے صحابہ کووہاں بھجوادیا اورپھر خود مدینہ میں بھی آپؐ پر ایمان لانے والے موجود تھے.پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر سالہاسال کہا ہے.تب بھی یہ ثبوت ہے کہ یہ کشف تھا.اوراگرصدیوں کہا ہے اور میرے نزدیک یہی کہا ہے.توپھر تویہ قطعی طور پر ثابت ہے.کہ ان
Page 562
الفاظ کوموسیٰ کے منہ سے نکلواکر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ موسیٰ کاروحانی سفر یعنی ان کی امت کا زمانہ صدیوں تک ممتدّچلاجائے گا.مجمع البحرین سے مراد زمانہ اختتام موسیٰ میرے نزدیک اس فقر ہ کے اس جگہ بیان کرنے کی بھی ایک حکمت ہے اورو ہ یہ کہ موسوی سفر کی اس منزل میں جہاں کہ فتٰی آپ کے ساتھ شامل ہونا مقدر تھا.ایک حصئہ قوم میں یہ خیال پیدا ہونے والاتھا کہ اب موسیٰ کاسفر ختم ہوگیا.اب اس نوجوان یعنی حضرت عیسیٰ کاسفر شروع ہوگا.یعنی بعض لوگوں میں یہ شبہ پیدا ہونے والاتھا.کہ حضر ت عیسیٰ کے آنے سے موسوی شریعت ختم ہوگئی.اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نیادین جار ی کیا ہے.ان الفاظ میں اس شبہ کاازالہ کیاہے اورموسیٰ ؑ کے منہ سے یہ کہلوایاہے کہ ا س نوجوان کے ملنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کاسفرختم نہیں ہوتا.بلکہ مجمع البحرین پر یعنی ظہورمحمد صلعم کے زمانہ پر جاکر ختم ہوگا.گویاعیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر کسی نئے دین کااجراء نہیں ہوگا.بلکہ وہ موسوی دین کی تائید کریں گے اورموسیٰ کے سفرکوختم کرنے والے نہ ہوںگے.بلکہ موسیٰ کی نیابت میں ان کے سفرکو پوراکریں گے.خود حضرت مسیح نے بھی اس امر کی تصدیق کی ہے.فرماتے ہیں.’’یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یانبیوں کی کتابوںکو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوراکرنے آیاہوں ‘‘.(متی باب ۵ آیت ۱۷) اس کشف سے معلو م ہو تاہے کہ یاتوحضرت موسیٰ نے جب یہ کشف دیکھا تواس کاشروع ہی یہ تھا کہ گویا وہ ایک راستہ پر ایک نوجوا ن کے ساتھ چل رہے ہیں.اورمنزل مقصود نہ ملنے پر حیران ہیں یایہ کہ اس سے پہلے بھی حصہ کشف کاتھا.جس میں لمبے سفر کا ذکر تھا مگراس کو بے ضرورت سمجھ کر قرآن کریم نے چھوڑ دیاہے.کیونکہ وہی آدمی یہ کہہ سکتاہے کہ جب تک مجمع البحرین تک نہ جاپہنچوں چلتاچلاجائوں گاخوا ہ صدیاں چلنا پڑے جو ایک عر صہ تک راستہ تلاش کرکے حیران ہورہاہو کہ منزل مقصود کہاں گئی.میرے نزدیک یہ اس امر کی دلیل ہے کہ وہ نوجوان حضرت مسیح تھے.جوموسوی سفرکے اختتام کے قریب آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے اورپھر اس روحانی سفر میں ان کے ہمرکاب ہوگئے.مجمع البحرین کے ظاہراً کسی مقام پر چسپاں ہونے کی تردید ا س آیت میں جو لفظ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ آیاہے یہ بھی اس پر روشنی ڈالتاہے کہ یہ کشفی واقعہ ہے.کیونکہ مجمع البحرین کسی معروف جگہ کانام نہیں.اورسوائے اس کے کہ اس کے معنے دوسمندروں کے ملنے کی جگہ کے لئے جائیں اورکوئی معنے ظاہر میں نہیں کئے جاسکتے.اور
Page 563
موسیٰ علیہ السلام کی ہجر ت کے بعد کی رہائش میں قریب ترین علاقے جہاںدوسمندر ملتے تھے یہ تین تھے.باب المندب.جہاںبحیرہ احمر اوربحرالہندملتے ہیں.دردانیال.جہاں بحیرہ روم اوربحیر ہ مارمور ہ ملتے ہیں یاپھر البحرین جہاں خلیج فارس کاسمندر بحرالہند سے ملتاہے.یہ تینوں علاقے قریباً ہزارہزار میل دور ان کے وطن سے تھے.اوراس زمانہ کے حالات کو مدنظر رکھ کر کوئی سال بھر کاسفربنتاتھا.لیکن چونکہ کشف سے معلوم ہوتاہے کہ سمندر کے کنارے کنارے آپ سفرکررہے تھے.اس لئے دردانیال کادرہ ہی ظاہری سمندر بنتاہے.کیونکہ تینوں جگہوں میں سے صرف وہی جگہ ہے.جس تک موسیٰ ؑ کی جائے رہا ئش ہے.سمندر کے کنارے کنارے راستہ جاتاہے.مگر یہی وہ راستہ ہے جس میں کنعان پڑتا ہے.اورجس کے متعلق بائیبل شاہد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زند گی میں وہاںنہیں جاسکے (استثناء باب ۳۴ آیت ۴،۵).پس یہ واقعہ بھی اس امر کاثبوت ہے کہ یہ ایک کشف تھا.مجمع البحرین کی تعبیر اورمجمع البحرین کسی جگہ کانا م نہیں بلکہ ایک تعبیر طلب نام ہے چنانچہ تعطیرالانام میں لکھا ہے.’’بَحْرٌ فی الْمَنَامِ یَدُلُّ عَلٰی مَلَکٍ قَوِیٍّ مَھَابٍ عَادِلٍ شَفِیْقٍ یَحْتَاجُ اِلَیْہِ الْخَلَائِقُ.اورپھر لکھاہے رُبَّمَا دَلَّ الْبَحْرُعَلَی التَّسْبِیْحِ وَالتَّھْلِیْلِ (تعطیر الانام کلمة البحر) سمندرسے مراد زبردست بادشاہ جوعاد ل ہو ، شفیق ہو ،اوردنیا اس کی محتاج ہو.اورایسا ہی سمندر کے معنے تسبیح و تہلیل کے بھی ہوتے ہیں.اوراس میں گویا ’’سُبْحٰنَ الَّذِيْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ ‘‘کی طر ف اشارہ ہے.پس مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ سے مراد درحقیقت و ہ زمانہ تھا.جہاں حضر ت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ختم ہوا.اورمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہوا.یعنی وہ گھڑی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلاالہام نبوت ہوا.مجمع البحرین تھی.وہاں موسیٰ جو ایک روحانی عادل،شفیق اوردنیاکے لئے ضروری بادشاہ تھے ان کاعلاقہ ختم ہوتاتھا اورمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اور بھی بڑے روحانی سمند ر تھے ان کا زمانہ شروع ہوتا تھا.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کشف میں دوبڑے سمندروں کے ملنے کا مقام دکھا کر گویایہ بتایاگیا کہ اس زمانہ تک آپ کی امت کا زمانہ ہے.آگے ایک اورسمندر شروع ہوتاہے.آپ کا زمانہ ختم ہوکر اس نئے نبی کاکام شروع ہوگا.اور وہی شخص روحانی زندگی کاسامان حاصل کرسکے گا جواس سمندر میں غوطہ لگائے گا.ا س رؤیا میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیاہے کہ موسوی سلسلہ محمدی سلسلہ کے لئے بطور ارہاص ہے.اورآخر یہ سمندراس سمندرمیں جاکرمل جائے گا.اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجوکشف دکھایاگیاتھااس میں تویہ نظارہ دکھایاگیا تھا کہ جبریل خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے.مگرحضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ
Page 564
نظارہ دکھایا کہ وہ مجمع البحرین کی طرف اپنے ساتھی کو لے کر گئے اوروہاں جاکران کاسفر ختم ہوگیا (درمنثور زیر آیت بنی اسرائیل ۱ تا ۸).فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ پس جب وہ(دونوں) ان(دونوں سمندروں کے)باہر ملنے کی جگہ پرپہنچے تووہ اپنی مچھلی (وہاں)بھول گئے.جس سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۰۰۶۲ پراس نے تیزی سےبھاگتے ہوئے سمندر میں اپنی راہ لی.حلّ لُغَات.اَلْحُوْتُ اَلْحُوْتُکے معنے ہیں اَلسَّمَکُ وَقَدْ غَلَبَ فِی الْکَبِیْرِ.مچھلی او رزیاد ہ تربڑی مچھلی پر بولاجاتاہے.(اقرب) اَلسَّرَبُ.اَلسَّرَبُ:حُجْرُالْوَحْشِیِ.وحشی جانور کے رہنے کی جگہ.اَلْحَفِیْرُ تَحْتَ الْاَرْضِ.زمین کے اندرگڑھا.القَنَاۃُ.یَدْخُلُ مِنْھَا الْمَاءُ.پانی کی نالی.نیز سَرَبٌ مصد ربھی ہے جس کے معنی تیزی سے چلنے کے ہیں (اقرب) تفسیر.حوت کی تعبیر نَسِيَا حُوْتَهُمَا.حوت کے معنے علم التعبیر میں یہ لکھتے ہیں’’رُبَّمَا دَلَّتْ رُؤْیَتُہُ عَلٰی مَعْبَدِ الصَّالِحِیْنَ وَمَسْجِدِ الْمُتَعَبِّدِیْنَ.‘‘(تعطیر الانام کلمۃ حوت) حوت یعنی مچھلی کادیکھنا بہت نیک لوگوں کی عبادت کی جگہ اورعبادت گزاروں کی مسجد پر دلالت کرتاہے.جیسا کہ اس آیت سے او راگلی آیت کے بعد کی آیت سے معلوم ہوتاہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین کے مقام کی شناخت یہ بتائی گئی تھی کہ وہاںمچھلی غائب ہوجائے گی.پس نَسِيَا حُوْتَهُمَاکے معنے یہ ہوئے.کہ جس مقام پر ان لوگوں کے ہاتھوںسے نیک لوگوں کی عبادت گاہیں اورعبادت گزاروں کی مساجد نکل جائیں گی.وہی مقام مجمع البحرین ہوگا.یعنی جہاں موسوی سلسلہ ختم ہوجائے گااورمحمدی سلسلہ شروع ہوگا.نَسِيَا حُوْتَهُمَا سے اشارہ ہے کہ موسیٰ اور ان کے فتی کی قوم سے عبادت کی قبولیت اٹھ جائے گی یہ مضمون کس قد واضح ہے.ایک نئے نبی کے آنے سے نیکی اورعبادت پہلی قوم سے چھین لی جاتی ہے.اوراس نبی کی قوم کی طرف منتقل ہوجاتی ہے.اسی کی طرف اس کشف میں اشارہ کیا گیا ہے اوربتایا ہے کہ سلسلہ محمدیہ کے اجراء پر
Page 565
بنی اسرائیل یعنی موسوی سلسلہ کے لوگوں کی عبادات خدا تعالیٰ کے حضو ر میں مقبول نہ رہیں گی.اورمحمد رسو ل اللہ کی امت کی عبادتیں ہی مقبول ہوں گی اورعبادت اورصلاحیت کے جوآثار ہیں موسوی سلسلہ کے لوگوں سے غائب ہوجائیں گے اورنَسِيَا حُوْتَهُمَا کہہ کر یہ بتایا ہے کہ خالص اسرائیلی قوم توا س وقت سے پہلے ہی صحیح عبادت اورتقویٰ کوکھوچکی ہوگی.صرف وہی قوم عبادت اورصلاحیت اپنے اندررکھتی ہوگی جوصرف موسی کی قوم نہیں کہلاسکتی.بلکہ موسیٰ اور اس کے فتی کی قوم کہلاسکے گی یعنی حضرت مسیح کے آنے کے بعد مسیحیوں میں عبادت رہ جائے گی.بنی اسرائیل اس سے محروم ہوجائیں گے.لیکن چونکہ حضرت مسیح حضرت موسیٰ کے سلسلہ ہی کے نبی ہوںگے.اس لئے ان کی حوت بھی ایک رنگ میں موسیٰ کی حوت ہوگی.اس لئے وہ دونوں کی طرف منسوب ہو گی.مگر مجمع البحرین کا مقام آئے گا تواس قوم کے ہاتھ سے بھی جن کے موسیٰ اورعیسیٰ علیھم السلام مشترک طورپر معلم ہوںگے.عبادت اورصلاحیت جاتی رہے گی.اس آیت سے بھی معلوم ہوتاہے کہ یہ کشف تھا.کیونکہ ظاہر مجمع البحرین توایسی جگہ ہوتی ہے کہ اسے کوئی بھول ہی نہیں سکتا اوراس کے لئے کسی حوت کی علامت کی ضرورت نہیں.پس یہ روحانی مجمع البحرین ہے جو علامتوںسے سمجھا جاسکتاہے.کیونکہ ظاہر میں اس کی کوئی علامت نہیںہوتی.بلکہ لوگ دوسرے بحر کے زمانے میں اس کی مخالفت کرتے اور اسے جھوٹاکہتے ہیں.اوریہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ مجمع البحرین آگیا ہے.یعنی پہلے نبی کا زمانہ ختم ہوگیا ہے اور دوسرے نبی کا زمانہ شرو ع ہوگیاہے.اس کی علامت یہی ہوتی ہے کہ پہلے نبی کی قوم کی عبادات اورصلاحیت جاتی رہتی ہے.اورعقلمند لوگ اللہ تعالیٰ کے سلوک میں اس فرق کو دیکھ کر کہ اب وہ پہلی قوم کی عبادات کی کوئی قد رنہیں کرتا اوردوسری قوم کی عبادتوںکو قبول کرتا اوراس کی دعائوں کوسنتاہے سمجھ جاتے ہی کہ مجمع البحرین آگیا ہے.اس مضمون کی طر ف قرآن کریم کی ایک اورآیت میں کھلے لفظوں میں بھی اشارہ کیاگیاہے فرماتا ہے.مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ١ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا١ٞ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ١ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ(الفتح :۲۹) یعنی محمد ؐ اللہ کے رسول ہیں.اوروہ لوگ جو ان کے ساتھ ہی کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں.اورآپس میں بہت رحم کرنے والے ہیں.توان کودیکھے گاکہ رکوعوںاور سجدوںمیں لگے رہتے ہیں.اوراللہ تعالیٰ کے فضل اورا س کی رضاکے متلاشی ہیں.ان کے مونہوں سے ان کے سجدوں کی قبولیت کے آثار ظاہر ہیں.یہ ان کی مثال تورات میں بیان ہوچکی ہے.اس آیت میں صاف
Page 566
بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے بتایاگیاتھا کہ محمد رسو ل اللہؐ اوران کی جماعت کی سچائی کاثبوت یہ ہوگاکہ ان کے چہروں سے یہ معلوم ہوگاکہ خداتعالی ٰ نے ان کے سجدوں کوقبول کرلیا ہے.جبکہ ان کے مخالفوں کی عبادتیں رد کردی جائیں گی.اوراللہ تعالیٰ کے فضلوں کے آثا ر ان کے چہروں سے ظاہر نہ ہو ں گے.اس کشف کو تورات سے تحریف کر کے یہود نے نکال دیا ہے میں اس آیت کو دیکھتے ہوئے سمجھتاہوں کہ تورات میں اس کشف کا ذکر تھا.مگریہود میں سے بعض نے جہا ں اورتحریفیں تورات میں کیں وہاں اسے بھی نکال دیا.کیونکہ اس سے ان کی قوم پر ایک زد پڑتی تھی.لیکن ان کی زبانی روایات میں ا س کشف کا ذکر باقی رہ گیاہے.جیساکہ یہود کے دوسرے لٹریچر میں اس کشف کابگڑی ہوئی صورت میں وجود پایا جاتا ہے.ا س آیت سے یہ بھی ثابت ہوتاہے کہ موسوی سلسلہ محمدی سلسلہ کی ایک کڑی تھا.کیونکہ مجمع البحرین کاظاہر میں کوئی نشان نہ ہونابتاتاہے کہ یہ دونوں سمندر اس طرح آپس میں ملے تھے.کہ دوسمندر نہ معلوم ہوتے تھے بلکہ اگلا سمندر پہلے کا تسلسل ہی معلوم ہوتاتھا.گویا پہلے سمندر کاپانی دوسرے میں آملاتھا.ایک دوسرے کے مقابل کے سمندر نہ تھےکہ ان کے ملنے کی جگہ کاالگ نشان نظر آتا.فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰىهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا١ٞ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ پھر جب وہ(اس جگہ سے )آگے نکل گئے تواس نے اپنے نوجوان (رفیق ) سے کہا (کہ)ہماراصبح کاکھانا ہمیں سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا۰۰۶۳ دے ہمیں یقیناً اپنے اس سفر کی وجہ سے تکان ہوگئی ہے.حلّ لُغَات.غَدَاءَ نا.اَلْغَدَاءُ کے معنے ہیں طَعَامُ الْغُدْوَۃِ.صبح کاکھانا(اقرب) نصبًا.نَصَبٌ کے معنے تھکان کے ہیں.مزید تشریح کے لئے دیکھو حجر آیت نمبر ۴۹.نَصَبٌ نَصِبَ(یَنْصَبُ) کا مصدر ہے.اورنَصِبَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں اَعْیَا.تھک گیا (لازم)نَصِبَ فِی الْاَمْرِ:جَدَّ وَاجْتَہَدَ.کسی کام میں کوشش اورمحنت کی (اقرب)پس النَّصَبُ کے معنے ہوں گے تکان.تفسیر.یہ ضروری نہیں کہ ان تمام واقعات کی تعبیر ہی کی جائے.کیونکہ بعض دفعہ کشف کی صورت میں بعض ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جوصرف رؤیا کوایک مکمل نظار ہ کی صورت دینے کے لئے شامل کئے جاتے ہیں.
Page 567
خود وہ تعبیر کے قابل امورکاحصہ نہیں ہوتے.مثلاً ایک شخص خواب میں ایک موت کا نظارہ دیکھتاہے تواس کے ساتھ کوئی مکان وغیرہ بھی دیکھ لیتا ہے.وہ مکان تعبیر طلب نہیں ہوتا.بلکہ صرف وہ نظارہ جس سے کسی کی موت پر دلالت کی جاتی ہے.تعبیر طلب ہوتاہے.لیکن اگر اس واقعہ کی بھی تعبیر ک جائے تومضمون میں وسعت ہی پیداہوتی ہے.اس لئے میں اس کی بھی علم تعبیر کے مطابق تشریح کردیتاہوں.غداء کے معنے علم التعبیر میں یہ لکھے ہیں کہ جو اپنا غداء طلب کرے.اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ تھک جائے گا.(تعطیر الانام زیر لفظ غداء ) ان معنوں کے روسے یہ مراد ہوگی کہ جب مجمع البحرین یعنی رسول کریم صلعم کا زمانہ آجائے گا توحضرت موسیٰ اورعیسیٰ کی قوم ا س سے فائدہ نہ اٹھائے گی (کیونکہ یقیناً ا س کشف میں موسیٰ اورعیسیٰ علیھما السلام سے مراد ان کی قومیں ہیں نہ کہ وہ خود.کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا.بلکہ ان کی قوم نے یہ زمانہ پایا )بلکہ ان کاانکار کرکے اپنے سفر کوجاری رکھے گی اوراپنے مذہب کے زمانہ کے ختم ہونے کو تسلیم نہ کرے گی.تب ایک لمبے سفر کے بعد وہ اپنے اند رتکان محسوس کرے گی حیران ہوگی کہ ہمیں جو کہاگیاتھا کہ ایک رسول کامل آنے والا ہے وہ کیوں نہیں آیا.اس وقت تھک کروہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ کہیں ہم سے غلطی تونہیں ہوئی.کہیں وہ آتو نہیں چکا.اورہم ا س کے ماننے سے محرو م تونہیں رہ گئے.قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّيْ نَسِيْتُ اس نے کہا (کہ )بتائیے (اب کیا ہوگا) جب ہم (آرام کے لئے )اس چٹان پر ٹھیرےتومیں مچھلی(کاخیال )بھول الْحُوْتَ١ٞ وَ مَاۤ اَنْسٰىنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ١ۚ وَ اتَّخَذَ گیا.اورمجھے یہ (بات )شیطان کے سواکسی نے نہیں بھلائی.اوراس نے سمندر میں عجیب طرح سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ١ۖۗ عَجَبًا۰۰۶۴ سے اپنی راہ لے لی.حلّ لُغَات.عجبًا.اَلْعَجَبُ کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر۳.
Page 568
الْعَجَبُ.اِنْکَارُمَا یَرِدُ عَلَیْکَ یعنے جب کوئی ایسا امر پیش آئے کہ اس کے ماننے میں طبیعت کو انقباض اور انکار ہو تو اس حالت انکار کو عجب کہتے ہیں.اِسْتِطْرَافُہُ.پیش آمدہ امر کو پسند کرنے کو بھی عجب کہتے ہیں.رَوْعَۃٌ تَعْتَرِی الْاِنْسَانَ عِنْدَ اسْتِعْظَامِ الشَّیْءِ.یعنی اس حالت رعب کو بھی عجب کہتے ہیں جو انسان پر کسی چیز کو بہت ہی بڑا سمجھنے کے وقت طاری ہوتی ہے.وَمِنَ اللہِ : الرَّضٰی اور جب اللہ کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا جاوے تو اس کے معنی پسندیدگی کے ہوتے ہیں.(اقرب) تفسیر.الصخرة کی تعبیر اور موسوی قوم کا فسق و فجور میں مبتلا ہونا الصَّخْرَۃُ:الْحَجَرُ الْعَظِیْمُ الصَّلْبُ(اقرب)یعنی عربی زبان میں بڑے اور سخت پتھرکوکہتے ہیں اورعلم تعبیر میں صخر ہ کے معنے لکھے ہیں.وَتَدُلُّ عَلٰی الْقِحَۃِ و الْفُجُوْرِ (تعطیر الانام المنام زیر لفظ صخرہ)یعنی خواب میں کوئی صخرہ دیکھے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ نہایت گندے فسق و فجور میں مبتلاہوگیا ہے.اس تعبیر کی روسے اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ کے معنے یہ ہوں گے کہ جب ہم فسق وفجو رمیں مبتلاہوگئے اورمیں بتاآیا ہو ں کہ اس کشف میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ؑ سے مراد ان کی اقوام ہیں.کیونکہ محمد رسول اللہ صلعم کا زمانہ انہوں نے پایا تھا نہ کہ خود حضرت موسیٰ اورحضر ت عیسیٰ ؑ نے.پس یہ تعبیر ہمیں دھوکے میں نہیں ڈال سکتی.مراد یہ ہے کہ جب و ہ قوم جو حضرت موسیٰ ؑ اور حضرت عیسیٰ کی مشترکہ تھی.فسق وفجور میں مبتلاہوجائے گی.وہی زمانہ مجمع البحرین کا ہوگایعنی اس وقت محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوںگے اور یہ ظاہر ہے کہ نبی تبھی دنیا میںآتے ہیں جبکہ اس وقت کے لوگ فسق و فجور میں مبتلاہوجاتے ہیں.پس ا س نظارہ کی تعبیر یہ ہوگی.کہ جب مسیحی قو م فسق وفجور میں مبتلاہوگئی تھی وہی وقت محمد رسول اللہ ؐ کے ظہور کاتھا.اوریہ خیا ل مسیحیوں کو ایک لمبے عرصہ کے بعد اپنے سفرمیں تھک جانے اوراپنی کوششوں میں ناکا م رہنے کے بعد پیدا ہوگا اوروہ افسوس کریں گے کہ ہم نے اس زمانہ کوکیوں کھودیا.وَ مَاۤ اَنْسٰىنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ نے اس مضمون کواوربھی واضح کردیا ہے یعنی محمد رسول اللہ کی پہچان سے ہم شیطانی وساوس کی وجہ سے محروم رہے.ورنہ جبکہ ہمار ی قو م کے ہاتھ سے عبادت کے ثمرات جاتے رہے تھے.اورہم فسق وفجور میں مبتلاہوگئے تھے.توکیوں ہم نے یہ نہ سمجھ لیا کہ اب مجمع البحرین کا مقام آگیاہے.اورہمار ی قوم سے خدا تعالیٰ نے اپنی مدد ہٹالی ہے.اورموعود نبی کا زمانہ آچکا ہے.اوروَ اتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِعَجَبًا.جو فرمایا اس میں وہ اپنی اس غلطی پر تعجب کرتے ہیں کہ حوت ہمارے ہاتھ سے نکل کر کس طرح دوسرے سمندر میں چلی گئی.یعنی عبادت کے ثمرات مسلمانوں کی طرف منتقل ہوگئے اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے.
Page 569
یہ نظار ہ بھی کشف پر دلالت کرتاہے.ورنہ مجمع البحرین کے سمجھانے کے لئے کسی ظاہر ی مچھلی کے نشان کی کوئی ضرورت نہ تھی.اوراگر ظاہری طور پر مچھلی کو دیکھ کر و ہ ونوں چل رہے تھے.توپھر بھولنے کے معنے ہی کوئی نہیں.کیا کبھی ا س دنیا میں ایسا ہواہے کہ مثلاً کوئی شخص موٹر میں سفر کررہاہو.پھر ایک لمباسفر طے کرنے کے بعد وہ بھول جائے کہ میں موٹر میں سفر کررہاتھا.اورپید ل سفرکرنے لگ جائے.اور کچھ دورجاکر اسے یہ بات یاد آئے.غرض جب مچھلی کے نشان پر و ہ چل پڑے تھے تو وہ ایک قدم بھی مچھلی کے بغیر نہ چل نہیںسکتے تھے.اس میں بھولنےکاکوئی امکان ہی نہ تھا.قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ١ۖۗ فَارْتَدَّا عَلٰۤى اٰثَارِهِمَا قَصَصًاۙ۰۰۶۵ اس نے کہا (کہ )یہی وہ (مقام )ہے جس کی ہمیں تلاش تھی.پھر وہ اپنے پائوں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے.حلّ لُغَات.نَبْغ.نَبْغِ بَغَاہُ کے معنے ہیں طَلَبَہُ اسے چاہا (اقرب)نَبْغِ جمع متکلم کاصیغہ ہے اس کے معنے ہوں گے کہ ہم چاہتے ہیں.تفسیر.یعنی اس موقعہ پر وہ سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے غلطی سے اپنا الگ سفر جاری رکھا.مجمع البحرین کو تووہ پیچھے چھو ڑآئے ہیں.فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ توانہوں نے ہمار ے(برگزید ہ)بندوں میں سے ایک ایسابندہ (وہاں)پایا جسے ہم نے اپنے حضور سے رحمت (کی عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا۰۰۶۶ سیرت)بخشی تھی.اوراسے ہم نے اپنی جناب سے (خاص )علم (بھی)عطا کیاتھا.تفسیر.عَبْدًا سے مرادآنحضرت ؐ ہیں عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤقرآن مجید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعبدٌ کے لفظ سے یاد کیاگیا ہے.سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہےوَاَنَّہٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰہِ یَدْعُوْہُ کَادُوْا یَکُوْنُوْنَ عَلَیْہِ لِبَدًا.(الجن :۲۰)کہ آپ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں.تولوگ آپ ہجوم
Page 570
کرکے امڈ آتے ہیں.صوفیاء نے تویہاں تک بحث کی ہے کہ عبدکا مقام سب درجات سے بڑادرجہ اوربلند مقام ہے اورسوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کامل عبد نہیں ہے.اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا میں بھی آپ کے وجود کی طرف اشار ہ فرمایا ہے.جیساکہ فرماتا ہے وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (الانبیاء :۱۰۸)یعنی ہم نے تجھے جہان کے لئے رحمت ہی رحمت بناکربھیجاہے.عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا.یعنی اس کو خاص علم دیاگیاہے جوپہلو ں کو نہ ملا.سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا(النساء :۱۱۴)کہ اے رسول ہم نے تجھے وہ کچھ سکھایاہے جوتوپہلے نہ جانتاتھا.اورتجھ پر اس ذریعہ سے بڑافضل کیاہے.اسی طرح فرماتا ہے.وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنْتُمْ وَ لَاۤ اٰبَآؤُكُمْ(الانعام :۹۲) یعنی اس نبی کے ذریعہ سے تم کو وہ علم عطا کیاگیاہے جواس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا.اور پہلوں میں موسیٰ و عیسیٰ بھی شامل ہیں.اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ عَلِيْمٍ (النمل :۷) یعنی تجھ کو قرآن حکیم اورعلیم خدا کی طرف سے سکھایاجاتاہے.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاسکھائی گئی ہے کہقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا(طٰہٰ :۱۱۵)یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)تواللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کر کہ الٰہی میراعلم اوربڑھا.میراعلم اوربڑھا.قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا موسیٰ نے اس سے کہا(کہ )کیامیں اس (مقصد کے )لئے آپ کے ساتھ چل سکتاہوں.کہ جوعلم آپ کو عطاہواہے عُلِّمْتَ رُشْدًا۰۰۶۷ اس میں سے کچھ رشد (کی باتیں)مجھے بھی سکھائیں.حل لغات.رُشْدٌ.رُشْدٌ حق کے راستے پراستقامت اختیار کرنارشد کہلاتاہے (اقرب) تفسیر.اس آیت سے موسوی مقام اورمحمدی مقام کامقابلہ کرکے دکھایاگیاہے اوربتایا ہے کہ موسوی مقام محمدی مقام کے تابع ہے اورجن امور کی تہ تک محمدی علوم پہنچے ہیں.ان تک موسوی علوم نہیں پہنچے.اور کشف میں ا س لطیف مقابلہ کو ایک مکالمہ اورمصاحبت کی صورت میں دکھایاگیاہے.
Page 571
قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا۰۰۶۸ اس نے کہا (کہ)تومیرے ساتھ رہ کر ہرگزصبرنہیں کرسکے گا.تفسیر.محمدی کمالات کی بلندی اس آیت میں گویا لن ترانی والے مضمون کو بیان کیاگیاہے کہ محمدی کمالات کی بلندی کو موسوی کمالات نہیں پہنچ سکتے.اوربتایا ہے کہ محمدی قوم کاصبر اورمرتبہ رکھتاہے اورموسوی قوم کاصبراور مرتبہ رکھتاہے.جن ابتلائوںاورمشکلا ت کامسلمانوں نے مقابلہ کیا موسوی سلسلہ کے لوگ وہاں آکر رہ گئے.ا س میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے.کہ گومسیحی سلسلہ کےلوگوںنے ایک لمبے عرصہ تک مشکلات برداشت کیں مگروہ مشکلات جسمانی تھیں.علمی آزمائیشیں نہ تھیں.علمی مشکلات کاوہ مقابلہ نہیں کرسکے.چنانچہ خود حضرت مسیح ؑ شاکی رہے کہ میرے مقام کوکوئی نہیں سمجھا.حتیٰ کہ انجیل میں تویہاں تک لکھا ہے.کہ مسیح ؑنے اپنی فلسطینی زندگی کے آخری سال میں جبکہ صلیب کاواقعہ قریب تھا.اپنے سب سے مقرب شاگرد پطرس سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں.اورجب انہوں نے بتایاکہ مَیں توآپ کومسیح سمجھتاہوں تووہ بہت خو ش ہوئے (متی باب ۱۶ آیت ۱۳.۱۹) جس سے معلوم ہوتاہے کہ اورتواورحواری بھی ان کومسیح ماننے کے لئے تیار نہ تھے.صرف ایک معمولی نبی سمجھتے تھے.پس پطرس کے ایمان کودیکھ کر ان کوخوشی ہوئی.آنحضرت ؐ کے صبر نفس کا مقابلہ موسوی قوم سے اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ ؑ کی طبیعتوںکابھی مقابلہ ہے.حضرت موسیٰ ؑ جلد سوال کرنے لگ جاتے.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے.یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ پر ہربات ظاہرکرتا.اوریہی فرق دونوں کی امتوں میں تھا.تورات پر نظر ڈالو.کہ بنی اسرائیل سوال پر سوال کررہے ہیں.مگرآنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کا یہ حال ہے کہ صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کیاکرتے تھے کہ کوئی اعرابی آوے.اورآنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے کوئی سوال پوچھے.تاہم بھی سن لیں.گویا اس قدر وقار اورصبر نفس حاصل تھا.کہ خود نہ پوچھا کرتے تھے.اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے.اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُىِٕلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ(البقرة :۱۰۹) کہ کیاتم سے بعض موسیٰ کی قوم کی طرح سوال کرناچاہتے ہیں.ایسانہ کرنا.وہ لوگ انہیں بار بار خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے پر اور ہر بات کے متعلق سوال کرنے کے لئے مجبورکیاکرتے تھے.چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہؓ نے ادب کے طریق کومضبوطی سے پکڑ لیا(بخاری کتاب العلم ).خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کایہ حال
Page 572
تھا کہ جو خدا تعالیٰ بتاتاسن لیتے ورنہ صبر سے انتظارکرتے.اوراس حکم پر عمل فرماتے کہ وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰۤى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ١ٞ وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (طٰہ:۱۱۵)یعنی قرآن کریم کواپنے وقت پر نازل ہونے دو.اور اس کی وحی کے آنے سے پہلے سوال نہ کیاکرو.اوریہ دعاکرو کہ الٰہی میرے علم کوبڑھاتارہ.وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا۰۰۶۹ اورجس بات کے علم کاتونے احاطہ نہیںکیا اس پر توصبر کر(بھی )کیونکرسکتاہے.حلّ لُغَات.لَمْ تُحْطِ بہٖ خُبْرًا کہتے ہیں اَحَاطَ بِہِ عِلْمًا اَیْ اَحْدَقَ عِلْمُہُ بِہِ مِنْ جَمِیْعِ جِھَاتِہِ وعَرَفَہُ.کسی بات کی خوب واقفیت اورآگاہی حاصل کی (اقرب)پس لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا کے معنے ہوں گے کہ جس بات کے علم کاتونے احاطہ نہیں کیا.تفسیر.یہود کے ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ اس میں اس طر ف اشار ہ ہے کہ موسوی سلسلہ کے لوگوں کے لئے محمدی علوم کاسمجھنا واقعہ میں مشکل ہوگا.کیونکہ ا س دین میں بہت سے مسائل نئے بتائے جائیں گے.اوراس شخص کے لئے جواپنے آپ کوعالم سمجھتاہو.نئی بات کوماننامشکل ہوتاہے.چنانچہ کفار جن کے دل صاف تختی کی طرح تھے.وہ تو بہت جلد آپ پر ایمان لے آئے.مگریہودونصاریٰ جن کے پاس خدا کاکلام موجود تھا محروم رہے.کیونکہ ہربات جواسلام میں ان کی کتب کے خلاف ہوتی تھی.ان کے صبر کے پیمانہ کوچھلکادیتی تھی.اوروہ ابتلاء میں پڑ جاتے تھے.حضرت مسیح ؑ کے وقت میں بھی اسی وجہ سے یہود ہدایت سے محروم رہے.اورغیرقومیں اصرار کرکے اس دین میں شامل ہونے لگیں.قَالَ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّ لَاۤ اَعْصِيْ لَكَ اس نے کہا (کہ )اگراللہ(تعالیٰ)نے چاہاتوآپ مجھے صابر پائیں گے.اورمیںآ پ کے کسی حکم کی اَمْرًا۰۰۷۰ نافرمانی نہیں کروں گا.تفسیر.موسیٰ ؑ نے کہاکہ تومجھے صابر پائے گا.اورمیں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا.اس آیت سے
Page 573
بھی ظاہر ہے.کہ یہ خواب تھی.کیونکہ حضرت موسیٰ ؑ جومستقل نبی تھے دوسرے شخص سے خواہ وہ کوئی ہو ،یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ امورروحانیہ میں میں تیری فرمانبرداری کروںگا.اس آیت میں یہ اشار ہ ہے کہ موسوی قوم میں سے جولوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کو پائیں ان کے لئے محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی اطاعت فرض ہے.اوراسی طرف حدیث میں ان الفاظ میں اشارہ موجود ہے.کہ لَوْکَانَ مُوْسٰی وَعِیْسٰی حَیَّیْنِ لَمَاوَسِعَھُمَا اِلَّااتِّبَاعِیْ.(ابن کثیرسورة آل عمران قولہ تعالیٰ و اذ اخذ اللہ میثاق)اگرموسیٰ اورعیسیٰ بھی زندہ ہوتے تووہ بھی میری پیروی کرتے.قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰۤى اس نے کہا (کہ)اچھا اگرتومیرے ساتھ چلے توتُوکسی چیز کے متعلق جب تک کہ میں اس کے متعلق تجھ سے ذکرکرنے اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًاؒ۰۰۷۱ میں پہل نہ کروں مجھ سے سوال مت کیجئیو.حل لغات.اُحْدِثُ: اَحْدَثَہُ کے معنے ہیںاِبْتَدَأَہٗ.اس کی ابتداکی پہل کی (اقرب) پس حتّٰی اُحْدِثَ کے معنے ہوں گے یہاں تک کہ میں پہل کروں.تفسیر.یعنی اس عبد نے کہا.کہ بہت اچھا چلو میرے ساتھ مگرجب تک میں خود نہ بولو ں تم نہ بولنا.یہ عجیب لطیفہ ہے.کہ موسیٰ سے پہلے سے اس قدرعہد لئے گئے.اورپھر بھی وہ پوچھتے چلے گئے.مگرمحمد رسول اللہ صلعم کے اسرا ء میںان سے جبریل نے کوئی عہد نہ لیا.مگرپھر بھی جب دنیااورشیطان کے تمثیلی وجودوں کے کرنے کے موقعہ پر جبریل نے آپؐ کو سوال کرنے سے روکا توآپؐ نے اس کی بات مان لی اورسوال نہ کیا(تفسیر ابن جریر سورۃ بنی اسرائیل ).حالانکہ آپ نے کوئی عہد نہ کیاتھا.اس سے بھی محمدی مقام اورموسوی مقام کافرق ظاہر ہوتاہے.
Page 574
فَانْطَلَقَا١ٙ حَتّٰۤى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا١ؕ پھر و ہ (دونوں وہاں سے )چل پڑے.یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے.تواس(خداکے برگزیدہ )نے قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا١ۚ لَقَدْ جِئْتَ اس میں شگاف کردیا.اس نے کہا(کہ )کیا آپ نے اس لئے شگاف کیا ہے کہ آپ اس کے اندر (بیٹھ کرجانے ) شَيْـًٔا اِمْرًا۰۰۷۲ والوں کو غرق کردیں آپ نے یقیناً (یہ)ایک ناپسندیدہ کام کیا ہے حلّ لُغَات.اِنْطَلَقَا.اِنْطَلَقَا اِنْطَلَقَ سے تثنیہ کاصیغہ ہے.اوراِنْطَلَقَ کے معنے ہیں.ذَھَبَ چلا گیا.(اقرب) پس اِنْطَلَقَاکے معنے ہوں گے وہ دونوں چل پڑے.خَرَقَہَا:خَرَقَہَا خَرَقَ الثَّوبَ کے معنے ہیں مَزَّقَہٗ کپڑے کو پھا ڑ دیا.(اقرب) اَلْخَرْقُ:قَطْعُ الشَّیْءِ عَلٰی سَبِیْلِ الْفَسَادِ مِنْ غَیْرِ تَدَبُّرٍ وَلَاتَفَکُّرٍ.کسی چیز کوخراب کرنے کے لئے.بغیر سوچے سمجھے کاٹ دینا (مفردات ) اِمْرًا الْاِمْرُ کے معنے ہیںالْعَجِیْبُ.عجیب.اَلْمُنْکَرُ.اوپرا.ناپسندیدہ (اقرب) تفسیر.آنحضرت کے اسراء اور موسیٰ کے اسراء میں فرق اس مقام سے حضرت موسیٰ کے اسراء کااصل واقعہ شروع ہوتا ہے.اورامت محمدیہ اورامت موسویہ کے حالات کامقابلہ کیاگیا ہے.استاذی المکر م حضرت مولوی نورالدین صاحبؓ فرمایاکرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور حضرت موسیٰ کے اسراء میں یہ فرق ہے کہ رسول کریم صلعم نے سوال سے پرہیز کیا.اورموسیٰ علیہ السلام نے صبر نہ کیا.اس سے بتایاگیاہے کہ محمد رسول اللہ صلعم کی امت صبر سے دین پر قائم رہے گی.اورحضر ت موسیٰ علیہ السلام کی امت بے صبری کرکے دین کو چھوڑ بیٹھے گی.یہ ایک لطیف نکتہ ہے اورواقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں.اسی طرح آپ فرماتے تھے کہ آنحضرت صلعم کے اسراء میں بھی تین واقعا ت دکھائے گئے تھے.اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسراء میں بھی تین ہی واقعات دکھائے گئے ہیں.مجھے اللہ تعالیٰ نے ا س پر مزید علم یہ بخشاہے.کہ صرف تین
Page 575
واقعات میں ہی مشابہت نہیں بلکہ دونوں کے اسراء میں جوواقعات دکھائے گئے ہیں.ان کی تعبیر بھی وہی ہے.اورصرف تمثیلی زبان میں فرق ہے ورنہ حقیقت ایک ہی ہے.اورہونابھی یہی چاہیے تھا کیونکہ موسوی اسراء میں محمدی ظہورکی خبر د ی گئی تھی.پس ضروری تھا کہ محمدی اسراء کے واقعات کی طرف اشارہ کیاجاتا.مجھے یاد نہیں کہ حضرت مولوی صاحب سفینہ کے کیامعنے کیاکرتے تھے.میں جوا س کے معنے کرتاہوں وہ مال کے ہیں.علم تعبیرالرؤیامیں سفینہ کی بہت سی تعبیریں لکھی ہیں.اوران میںسے ایک تعبیر مال ہے(تعطیر الانام زیر لفظ سفینۃ ) میرے نزدیک اس کشف میںیہی تعبیرمراد ہے اورقرآن کریم بھی اسی کی تصدیق کرتاہے کیونکہ قرآن کریم میں آتاہے رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ١ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.(بنی اسرائیل :۶۷)یعنی تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لئے سمندر میں کشتیاںچلائی ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل کویعنی مال ودولت کوحاصل کرو.وہ تم پر بہت مہربان ہے.پس میر ے نزدیک سفینہ سے مراد دنیاوی مال ہیں.اورکشتی میں دونوں کے سوار ہونے سے مرا د یہ ہے کہ دونوں کی امتوں پر ایک وقت ایساآئے گاکہ انہیں دنیو ی مال بافراغت ملے گا.آگے لکھا ہے جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے توا س ساتھی نے کشتی کوپھاڑ دیا.خَرَقَ الثَّوْبَ کے معنے ہوتے ہیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کردیا.خَرَقَھَا کے معنے ہوئے.اس کے تختے نکال کرکشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کردیا.اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یادوسرے لفظوں میں ان کی قوم نے اعتراض کیا کہ کیا تیرامنشاء یہ ہے کہ کشتی کے سوار غرق ہوجائیں.تونے یہ بہت بُراکام کیا ہے.خرق سفینہ سے مراد میرے نزدیک خرق سفینہ سے مراد یہ ہے.کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی دنیاکوبہت سے شرعی احکام سے چھید ڈالا ہے.مثلاً اول زکوٰ ۃ کاحکم دیاہے.جس سے مال کم ہوتاہے پھر صدقات کاحکم دیاہے پھر سود سے منع کرکے دولت کونقصان پہنچایاہے.پھرورثہ کاحکم دے کرمال کوتقسیم کردیاہے.اوردولت کو بڑھنے سے روک دیا ہے.گویا دنیا داروں کی نگاہوں میں اپنی قوم کی دنیاوی زندگی تبا ہ کردی ہے اورنیکو کاروں کی نگہ میں قوم کو دنیا کی محبت کے بداثرات سے اورقوم کو امراء کی غلامی سے بچالیا ہے.یہ تعلیم موسوی سلسلہ کے لوگوں پر سخت گراں گزرتی ہے یہود پر بھی اورنصاریٰ پربھی.کیونکہ گونصاریٰ منہ سے تویہی کہتے ہیں کہ سوئی کے ناکہ میں اونٹ کاگزرجاناآسان ہے لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا بہت مشکل ہے(مرقس باب۱۰ آیت ۲۵)لیکن عمل ان کایہ ہے کہ ان کے ممالک کے سب قوانین دولت مندوں کے اموال بڑھانے میں ممدہیں.
Page 576
زکوٰۃ کاکوئی حکم ان میں نہیں.سود کی کھلی اجازت ہے جوئے کی اجازت ہے جائیداد کوبہت سے ورثاء میں تقسیم کرنے کاکوئی حکم نہیں.بہت سے امراء اپنے بڑے بیٹوں کودولت سپرد کرکے خاندان کی دولت کو بڑھاتے جاتے ہیں.اسی طرح ان کی شریعت میں مزدوروں کے حقوق کی حفاظت نہیں.حالانکہ اسلام نے اس کےلئے بھی قواعد مقرر کئے ہیں تاکہ چندامراء غرباء کوغلام بنا کر اپنے اموال نہ بڑھاتے رہیں.ان امتیازات کی وجہ سے یہود اورنصاریٰ اسلام میں داخل ہونے سے کتراتے ہیں اورسمجھتے ہیں کہ اسلام نے قوم کو غرق کرنے کی راہ کھول دی ہے.جس طرح یہ پہلاسبق ہے.جواسراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوملا ہے بالکل اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواسراء کے دن پہلے ایک بڑھیا دکھائی گئی.اوراس کے بعد جب پیالے پیش ہوئے توان میںسے پہلاپیالہ پانی کاتھا.اور حضرت جبریل نے عورت کی بھی یہی تعبیر کی.کہ یہ بڑھیا دنیاتھی اورپانی کی بھی یہی تعبیر کی.کہ یہ مال تھا.کیونکہ انہوں نے کہاکہ اگر تُو پانی پی لیتا توتوبھی غرق ہوجاتا اورتیری امت بھی غرق ہوجاتی.یعنی دنیا کے کاموں میں منہمک ہوجاتی اوراللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑجاتا.آنحضرت ؐ کی قوم اور موسیٰ کی قوم کے خیالات میں فرق دیکھو حضرت موسیٰ کی قوم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالا ت میں کتنا فرق ہے.رسول کریم صلعم کوتوجبریل یہ کہتا ہے کہ اگرتوپانی پی لیتاتوتیری قوم غرق ہوجاتی.گویا وہ بے عیب سفینہ کو یعنی دنیاوی زندگی کو غرق ہوناقراردیتے ہیں.لیکن حضرت موسیٰ یادوسرے لفظوں میں ان کی قوم ٹوٹی ہوئی سفینہ کا یعنی زکوٰۃ وغیر ہ قواعد سے دنیاوی اموال کے چندہاتھوںمیں جمع ہوجانے کوروکنے کانام قوم کاغرق ہونارکھتے ہیں.جہاں اس قدراختلاف آراء ہو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کس طرح ہو سکتا ہے.اورایک فریق دوسرے کی معیت پر کب تک صبر کرسکتاہے.قرآن کریم سے معلوم ہوتاہے کہ جس طرح اس کشف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبداللہ پراعتراض کیا ہے کہ کشتی کے پیندے میں سوراخ کیوں کیا.اسی طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پراعتراض کیا ہے کہ چندے وغیر ہ لے کرقوم کوتبا ہ کیوں کرتے ہو.چنانچہ قرآن کریم میں یہود کایہ اعتراض ان الفاظ میں بیان ہواہے.وَقَالَتِ الْیَھُوْدُ یَدُ اللّٰہِ مَغْلُوْلَۃٌ (المائدۃ :۶۵)یعنی یہود چندوں وغیرہ کے مطالبات کو دیکھ کرکہتے ہیں کہ خوامخواہ انہوں نے قو م پر بوجھ ڈال دیا ہے.کیا خدا تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ہے کہ ہمارے محدود اموال کووہ خرچ کرائے گا جس کو اس نے دیناہوگاخود دےدےگا.دوسرے لوگوں سے غرباء کی خدمت کیوں کروائی جاتی ہے.گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہ کشتی والوں کی کشتی کوکیوں چھیداجاتاہے.اسی طرح عام کفار کے متعلق بھی قرآن میں آتاہے.اوران میں یہود ونصاریٰ سب
Page 577
ہی شامل ہیں کہ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ١ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗۤ١ۖۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (یٰس :۴۸) یعنی جب لوگوں کو محمدرسول اللہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جوتم کومال دیا ہے وہ صرف تمہارے لئے نہیں ہے سب دنیاکے لئے ہے.اسے اللہ تعالیٰ کے غریب بندوں پر خرچ کرو.تووہ آگے سے مسلمانوںسے کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ خود ان کو نہیں کھلا سکتا.پھر جب خدا نے باوجود بڑے خزانوںکے ان کو نہیں کھلایا.توہم کس طرح ان کو اپنے اموال میں سے حصہ دیں.اورپھر یہ کہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی بے راہ ہو کہ اس طرح اپنے اموال کو تباہ کرتے ہو.پس یہ اعتراضات اسلام کی تعلیم پریہود اور دوسرے کفار کی طرف سے بکثرت ہوتے رہے ہیںاورآج تک ہورہے ہیں.لیکن خدا کاعاشق ٹوٹی ہوئی کشتی میں ہی اس دنیاکاسفر کرنازیاد ہ پسند کرتاہے بہ نسبت اس سلامت کشتی کے جو ا س کے دل سے خدا تعالیٰ کی یاد کو بھلادے.نصارٰی کے لئے مالی قربانی ابتلاء نصاریٰ کے لئے یہ ابتلاء سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہ زیادہ مالدار ہیں.اس آیت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ کشف ہے ورنہ جب کشتی میں چھیدکیاتھا توکشتی غرق کیوں نہ ہوجاتی.قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا۰۰۷۳ اس (برگزیدہِ خدا)نے کہا.(کہ)کیا میں نے (تجھے )کہانہیں تھا (کہ)تومیر ے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کرسکے گا.تفسیر.یعنی میں نے توپہلے سے ہی کہہ د یا تھا کہ میری تعلیم اور تمہار ی تعلیم میں زمین و آسمان کا فرق ہے تم لوگ میرے ساتھ سفرنہیں کرسکتے جب تک اپنے نفوس کو بالکل مار نہ دو.
Page 578
قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَ لَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اس نے کہا (کہ اس دفعہ)آپ مجھ پر گرفت نہ کریں کیونکہ میں (آپ کی ہدایت کو)بھو ل گیاتھااورآپ میری اَمْرِيْ عُسْرًا۰۰۷۴ (اس )بات کی وجہ سے مجھ پرسختی نہ کریں.حلّ لُغَات.تُرھِقْنِیْ.اَرْھَقَہٗ عُسرًا کے معنے ہیں کَلَّفَہٗ اِیَّاہ.اس پر سختی کی (اقرب) پس لَا تُرْھِقْنِیْ مِنْ اَمْرِیْ عُسْرًا کے معنے ہوں گے کہ آپ مجھ پر میری بات کی وجہ سے سختی نہ کریں (اقرب) تفسیر.یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اس دفعہ معاف کرو.پھر ایسی بات نہ کروں گا.اس آیت میں بتایا ہے کہ شروع شروع میں یہود و نصاریٰ محمد رسول اللہ صلعم سے صلح کریںگے مگربعد میں اعتراضات شروع کردیں گے اورآخرقطع تعلق ہوجائے گا.چنانچہ جب آپؐ مدینہ تشریف لائے توپہلے یہود نے آپ سے صلح کی اورآپ کی پار ٹی میں شامل ہوئے.مگر جب ان قربانیوں کودیکھا جوآپ کےساتھ مل کر کرنی پڑی تھیں توجھگڑاشروع کردیا چنانچہ بنوقینقاع نے آپ سے اس بات پراختلاف کیا کہ ایک تاوان جوبعض مسلمانوں پر پڑاتھا اورجس میں حصہ لینا معاہدہ کے روسے یہودپربھی فرض تھا.اس میں حصہ لینے کے لئے یہود کو کیوں کہاجاتاہے (سیرۃ الحلبیۃ غزوۃ بنی النضیر ).نصاریٰ کابھی یہی حال تھا.شروع شروع میں وہ مسلمانوں سے اچھے تعلقات رکھتے تھے.حتی کہ آپؐ نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھے توقیصر نے شروع میں آپؐ کی تعریف کی(بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی).لیکن بعد میں جب دیکھا کہ اسلامی سیاست مسیحی سیاست سے ٹکراتی ہے تواسلام سے جنگ شروع کردی.جس کاخمیازہ اس نے حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایسا بھگتا کہ صدیوں تک ا س کا اثر نہ مٹا.فَانْطَلَقَا١ٙ حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ١ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ پھر و ہ(دونوں وہاں سے )چل پڑے یہاں تک کہ وہ جب ایک لڑکے کوملے تواس(خداکے بندہ)نے اسے مارڈالا.
Page 579
نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ١ؕ لَقَدْ جِئْتَ (اس پر )اس نے(یعنی موسیٰ نے )کہا(کہ )کیا (یہ سچ نہیں کہ )آپ نے (اس وقت )ایک پاکباز(اوربے گناہ) شَيْـًٔا نُّكْرًا۰۰۷۵ شخص کوکسی(کے خون)کے عوض کے بدوں (ناحق ہی)مارڈالاہے.آپ نے یقیناً (یہ)بہت براکام کیا ہے.حلّ لُغَات.نُکْرًا.اَلنُّکْرُ :اَلْمُنْکَرُ.ناپسندیدہ بات.اَلْاَمْرُ الشَّدِیْدُ.مشکل کام.اَلْقَبِیْحُ برا(اقرب) زَکِیَّۃٌ.یہ زَکیٰ(یَزْکُوْ)سے فعیل کے وزن پر ہے.اور زَکَی الشَّیْءُ کے معنی ہیں.نَمَا.اس چیز نے نشوونما پائی.زَکَی الرَّجُلُ.صَلُحَ وہ نیک و پاک ہوگیا.تَنَعَّمَ وَکَانَ فِیْ خِصْبٍ.خوب نازونعمت اورآسودگی میں ہوگیا.بیضاوی نے غُلَامًازَکِیًّا کے معنے طَاھِرًامِنَ الذُّنُوْبِ نَامِیًا عَلَی الْخَیْرِ کے کئے ہیں یعنے گناہوں سے پاک اور نیکی میں نشوونماپانے والالڑکا (اقرب) تفسیر.اس موقعہ پربھی حضرت استاذ ی المکرم یہ توجہ دلاتے تھے کہ اسراء کی حدیث میں آنحضرت صلعم کو جب جبریل بار با ر اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ کالفظ کہتے تھے (خصائص الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۱۵۴،۱۵۵)موسیٰ کے واقعہ میں بھی اِنْطَلَقَ کالفظ بار بار آیا ہے.پس یہ بھی دلیل ہے کہ یہ اسراء روحانی تھا.قتل سے مراد حضرت خلیفہ اول کے نزدیک حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ.جب ایک نوجوان کوملے تواسے اس ساتھی نے قتل کردیا.حضرت استاذی المکر م فرماتے تھے.اس جگہ ان اعتراضو ںکی طرف اشار ہ کیا ہے.جوموسوی امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پرکرنے والی تھی.کہ کعب بن اشرف وغیرہ کو انہوں نے کیوںقتل کروایاہے اوراس کاجوب دیاہے.میرے نزدیک یہ نظارہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نظارہ کے مشابہ ہے اوراسی کے ہم معنی ہے.رسول کریم صلعم نے واقعہ اسراء میں بڑھیاکے دیکھنے کے بعد دیکھاتھا کہ کوئی شخص آپؐ کو اپنی طرف بلاتا ہے مگرآپ نے اسے جواب نہ دیا.نیز اس نظارہ کی تشریح کے لئے آپ کے سامنے شراب کاپیالہ پیش کیاگیا.جس کے پینے سے آپؐ نے انکار کردیا.اورجبریل نے ا س آدمی کی تعبیر شیطان کی.اوراس پیالہ کی تعبیر غوایۃ.جوشیطان کاکام ہے.اسی طرح دوسرانظارہ حضرت موسیٰ کوغلام کادکھایاگیاہے.جس کو محمدی
Page 580
جمال نے قتل کردیا.نوجوان کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اب ہم علم تعبیر رؤیا میں نوجوان آدمی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر دیکھتے ہیں.توعلاوہ اورتعبیروں کے ایک تعبیر یہ لکھی ہے ’’تَدُلُّ عَلَی الْحَرَکَۃِ وَالْقُوَّۃِ وَالْجَہْلِ(تعطیرا لانام زیر لفظ الشاب ) یعنی خواب میں نوجوان مرد کو دیکھے تواس کے معنے قوت نشاط اورجہالت کے ہوتے ہیں اوریہی امورانسان کوشیطان کے پیچھے چلانے والے ہوتے ہیں.یعنی ایک طرف طاقت ہو.دوسری طرف سیر تماشے دیکھنے کی خواہش ہو.اور تیسری طرف علم روحانی سے ناواقفیت ہو.یہ تین چیز یں جب جمع ہوجاتی ہیںتوانسان شیطان کے پیچھے چل پڑتا ہے.پس یہ دونوں نظارے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ ؑ کے اسراء میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں.مسیحیوں کے نزدیک اسلام انسانی جذبات کا خون کرتا ہے اوریہ جودکھایاگیاکہ اس عبد نے اس غلام کو مار دیا.اوراس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی دوسر ی تعلیم جو نصاریٰ کے لئے قابل اعتراض ہوگی وہ اسلام کالغو اموراورلہوولعب اورشراب سے روکناہوگا.اس پر موسوی سلسلہ کے لوگ (یعنی خصوصاً مسیحی.کیونکہ میں بتاچکاہو ں کہ دوسراساتھی جوحضرت موسیٰ نے دیکھاہے وہ حضرت مسیح ہیں.اورمجمع البحرین کے پاس حضرت موسیٰ ؑ کی وہی امت باقی تھی جو حضرت مسیح ناصر ی کے ذریعہ سے آپ کوملی تھی.ہاں دوسرے درجہ پر یہودبھی اس میں شامل ہیں )یہ اعتراض کریں گے کہ اسلام جوانی کومار تاہے اورانسان کوزندگی کالطف لینے نہیں دیتا.اوریہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں زندگی کامزہ لینے کے لئے دی ہیں نہ اس لئے کہ ان کو تباہ کردیاجائے.چنانچہ غورکرکے دیکھ لو کہ ان شیطانی اعمال کی وجہ سے بالعموم مسیحی لوگ اسلام سے متنفر ہیں کیونکہ ا س میں انہیں ان شیطانی افعال سے روکاگیاہے اور ان کے نزدیک گویا جوانی کااسلام نے خون کردیاہے.قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا۰۰۷۶ اس (خداکے پیارے )نے کہا (کہ)کیامیں نے تجھے کہانہیں تھا (کہ)تومیرے ساتھ رہ کرہرگزصبر نہیں کرسکے گا.تفسیر.یہ آیت بھی ثبوت ہے اس کا کہ یہ کشف ہے کیونکہ جاگتے ہوئے کسی کو بلاوجہ قتل کردینا قطعاً حرام ہے.
Page 581
قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍۭ بَعْدَهَا فَلَا تُصٰحِبْنِيْ١ۚ قَدْ اس نے کہا(کہ)اگر اس کے بعد میں نے کسی بات کے متعلق آپ سے پوچھا تو(بیشک)آپ مجھے اپنے ساتھ نہ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّيْ عُذْرًا۰۰۷۷ رکھئے گا (اس صورت میں)آ پ یقیناً میر ی طر ف سے معذور سمجھے جانے کی حد تک پہنچ چکے ہوں گے.تفسیر.یعنی اب کی دفعہ جانے دواور تعلق نہ توڑو.پھر ایسا ہی کیاتوتعلق توڑ دینا.اس میں بھی ا س طرف اشارہ ہے کہ یہود اورنصاریٰ بار بار مسلمانوں سے معاہدات کریں گے لیکن پھر ان کوتوڑدیں گے اوروہ عداوت جو انہیں اسلام سے ہے ان پر غالب آجائے گی.فَانْطَلَقَا١ٙ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَيَاۤ اَهْلَ قَرْيَةِ ا۟سْتَطْعَمَاۤ اَهْلَهَا پھروہ (وہاں سے بھی ) چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی کے لوگوںکے پاس پہنچے تواس (بستی )کے فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ باشندوںسے انہوںنے کھانامانگامگرانہوں نے انہیں (اپنے)مہمان بنانے سے انکار کردیا پھر انہوں نے اس يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ١ؕ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ (بستی)میں ایک ایسی دیوار پائی جوگرنے کوتھی.اس (خداکے بندہ)نے اسے درست کردیا (اس پر )اس نے اَجْرًا۰۰۷۸ (یعنی موسیٰ نے )کہا(کہ )اگرآپ چاہتے تویقیناً اس کی کچھ (نہ کچھ)اجرت لے سکتے تھے.تفسیر.اہل قریہ کے ضیافت سے انکار کی تعبیر اَهْلَ قَرْيَةِسے مراد قوم ہے کیونکہ قوم کوجب دکھایاجاتاہے گائوں کی شکل میں دکھایاجاتاہے اورضیافت کی تعبیر تعاون ہوتی ہے لکھاہے ضَیَافَۃٌ خواب میں
Page 582
اِجْتِمَاعٌ عَلٰی خَیْرٍ کے معنے رکھتی ہے.(تعطیر الانام زیر لفظ الضیافۃ )یعنی کسی نیک کام میں باہم تعاون کرنے کا فیصلہ ضیافت کی شکل میں دکھایاجاتاہے پس ’’دونوں نے کھانامانگا‘‘کی تعبیر یہ ہوگی کہ دونوں نے تعاون کی درخواست کی.اورضیافت کے انکار کے معنے ہوں گے کہ قوم نے دونوں کے سوال کے جواب میں تعاو ن کرنے سے انکارکردیا.دیوار بنانے کی تعبیر اور اس سے استدلال اس کے بعد لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دیواردیکھی جوگرنے کو تھی.تعطیر الانام میں لکھاہے کہ جب کوئی دیوار دیکھے جس میں خرابی ہوگئی ہو تواس سے مراد کوئی عالم یا امام ہوتاہے جس کامال جاتا رہتاہے.پھر اگریہ دیکھے کہ اس کی مرمت کردی گئی ہے تواس کے یہ معنی ہوں گے کہ اس عالم کے کام کودرست کردیاجائے گا.اوراگردیکھے کہ مرمت نہیں کی گئی توا س کاکام تباہ ہوجائے گا اورنیز امام ابن سیرین کے تعبیر نامہ میں لکھاہے کہ دیوار کے کچھ حصہ میں خرابی دیکھ کر اسے درست کرنے کی تعبیر اس جگہ کے والی کی بجائے دوسرے والی کامقرر ہوناہوتاہے (زیر لفظ حائط).ان تعبیروں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سارے نظار ہ کایہ مطلب ہو گا کہ حضرت موسیٰ ؑ اوروہ اللہ کابندہ جس کے ساتھ وہ چلے تھے ایک جماعت سے تعاون چاہیں گے مگر و ہ تعاون نہ کرے گی.اوروہ کسی بزرگ کے کام کوخراب ہوتادیکھیں گے.اس پرموسیٰ علیہ السلام توخاموش رہیں گے لیکن وہ عبداللہ اس کام کودرست کردے گایایہ کہ اس قوم کے لئے دوسراحاکم مقررہوجائے گاموسیٰ علیہ السلام اس امر کو دیکھ کرکہیں گے کہ اس پرکوئی اجر لیتے تواچھاہوتا مگروہ اس بات کو سن کرناراض ہوجائےگااورکہے گاکہ بس اب ہماراتمہاراتعلق ختم ہے.اس حصہ کی تعبیر حضرت استاذی المکر م مولوی نورالدین صاحب یہ فرمایاکرتے تھے کہ یاتو اوس اورخزرج مراد ہیں کہ دیرسے یہ قومیں ترقی سے محروم تھیں.اللہ تعالیٰ رسول کریم صلعم کومدینہ لے گیا.اوران کے لئے بھی ترقی کی راہیں کھل گئیں یافرماتے تھے کہ مرادحضرت اسمٰعیل اور حضرت اسحاق کی اولاد ہے کہ ان کاکام خراب ہورہاتھا ایک کے حق کی حفاظت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کردی.اور دوسرے کے حق کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے.میری رائے میں ا س نظارے کاپہلاحصہ بتاتاہے کہ قریہ سے مراد عالم یہودیت اورنصرانیت ہے.جب اس سے تعاون کی درخواست کی گئی تواس نے انکار کردیا.اوردیوارسے یہود ونصاریٰ کے بزرگ مراد ہیں.اوراس کے گرنے کے قریب پہنچنے سے مراد ان کے بزرگوںکااثر زائل ہونا ہے اورمرمت کرنے کے یہ معنے ہیں کہ ان کی تعلیم کو پھر سے قائم کردیا اوران کے اند رایک نیا والی یاحاکم مقررکردیا.
Page 583
اجرت نہ لینے پر اعتراض کرنے سے یہود کی تجارتی حرص کی طرف اشارہ ہے اورموسیٰ علیہ السلا م نے جوکہا کہ اجر کیوں نہ لے لیا.اس سے مراد یہ ہے کہ موسوی قوم میں تجارتی حرص بہت بڑھ جائے گی اوروہ ہراک کام کو اس کے دنیوی فائدہ کاانداز ہ لگاکر کریں گے اورخالصۃً للہ کام کرنا ان کے لئے مشکل ہوگا.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسوی سلسلہ کی آخر ی کڑی یعنی مسیحیت کایہ حال ہے کہ ان کی تعلیم بھی دنیوی اغراض سے ہوتی ہے.ان کی ہمدردی بھی دنیوی اغراض سے ہوتی ہے.حتی کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں تواس میں بھی سیاسی اوردنیوی فوائد مدنظر ہوتے ہیں خالصۃً للہ کام جس میں کوئی دنیاوی خیال مدنظر نہ ہو.ان میں قریباً مفقود ہے.دعوت سے انکار میں یہود کے حضرت موسیٰ سے عدم تعاون کی طرف اشارہ ہے یہ جو فرمایاکہ اہل کتا ب سے اپنے کاموں میں تعاو ن کی خواہش کی توانہوں نے انکا رکردیا.اس کی مثال حضرت موسیٰ کی زندگی میں تویہ موجود ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو کنعان کاملک دیئے جانے کاوعدہ دے کر مصر سے لائے اور کئی چھوٹی اقوام سے جنگیں ہونے کے بعد ان کو اہل کنعان پر حملہ کرنے کاحکم دیا توانہوں نے حضرت موسیٰ کاساتھ دینے سے صاف انکار کردیا.چنانچہ قرآن کریم میں آتاہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے جواب میں انہوں نے کہا.قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (المائدۃ :۲۵)یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب وقت آگیاہے کہ دشمن پر حملہ کرکے موعود ملک کو لیاجائے توانہوں نے جواب دیاکہ وعدہ یاخدا کاتھایاتمہاراتھا ہم اس وعد ہ کے پوراکرنے کے لئے کیوں اپنی جانیں گنوائیں.اے موسیٰ تم اور تمہاراخداجاکر لڑو.اوراپنے وعدہ کو پوراکرو.ہم تواپنی جگہ سے نہ ہلیں گے ہاںجب آپ دونوں ا س ملک کوفتح کرلیں گے توہم بھی ملک میں داخل ہوجائیں گے اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قو م نے عین اس وقت جب اللہ تعالیٰ کاوعدہ پوراہونے کو تھا ایک لغو عذر کی بناء پر حضرت موسیٰ ؑ سے تعاون کرنے سے انکار کردیا.حالانکہ اللہ تعالیٰ کے بعض وعدے اس کے بندوں کے ذریعہ سے پورے کرائے جاتے ہیںاوربندوں کافرض ہوتاہے کہ اس قسم کے وعدوں کے پوراکرانے میں انبیاء سے تعاون کریں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے عدم تعاون کی مثال قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی ہے قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ١ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (آل عمران:۶۵)یعنے اے محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود ونصاریٰ کویہ دعوت دے کہ آئواپنی ضدیں چھوڑ کر ایک بات میں توہم سے مل کرکام کرو اوروہ یہ کہ ہم سب مل کرتوحید کوقائم
Page 584
کریں نہ خدا تعالیٰ کے سواکسی اَورکی عبادت کریں اورنہ عقیدۃً اس کاکسی کوشریک قرار دیں اورنہ ناواجب طورپر جتھا بند ی کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق عدل اورانصاف سے دنیا میں کام کریں(گویا اللہ تعالیٰ اوربندوں سے صلح رکھنے کے بارہ میں اشتراک عمل کرنے کی ان سے درخواست کر )پھر فرماتا ہے کہ اگریہ لوگ ایسی منصفانہ بات بھی نہ مانیں اوراس مشترک پروگرام پر عمل کرنے اورتعاون کرنے کے لئے تیار نہ ہو ں تواے مسلمانو !تم ہی ہمارے رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان یہودونصاری سے کہہ دینا کہ جائو تم تعاو ن نہیں کرتے تونہ کروہم اپنے خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے رسولؐ سے تعاون کریں گے.اورعیسائیوں نے حضرت مسیح سے تعاون نہ کیا.عیسائیوں نے حضرت مسیح سے تعاون نہ کیا اگر غورسے دیکھا جائے تومسیح کی قوم نے بھی ان سے تعاو ن نہیں کیا کیونکہ صلیب کے موقعہ پر سب لوگ حضرت مسیح کوچھو ڑ کربھاگ گئے.قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِيْ وَ بَيْنِكَ١ۚ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَا اس (خداکے برگزیدہ)نے کہا(کہ)یہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان جدائی (کا وقت)ہے.جس بات لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا۰۰۷۹ پرتوصبر نہیں کرسکا میںابھی تجھے اس کی حقیقت سے آگاہ کرتاہوں.تفسیر.یعنی عبداللہ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ برابر اعتراض ہوتے ہی چلے جاتے ہیں توا س نے کہہ دیاکہ ہم آپس میں جداہوتے ہیں.اس میں اس طرف اشارہ کیاگیاکہ باوجوددعوتِ اشتراک اور توحید کے نقطہ پر جمع ہوجانے کی درخواست کے جب اہل کتاب باز نہ آئیں گے اوراپنے شرک کو نہ چھو ڑیں گے تومحمدرسو ل اللہؐ یہود اورنصاریٰ سے قطع تعلق کرلیں گے اور آپس میں مقابلہ شروع ہوجائےگا.اَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِ کشتی توچند مساکین کی تھی جودریا میں کام کرتے ہیں اوران کے سامنے (دریاپار)
Page 585
فَاَرَدْتُّ اَنْ اَعِيْبَهَا وَ كَانَ وَرَآءَهُمْ مَّلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ ایک (ظالم )بادشاہ تھاجوہرایک کشتی کو زبردستی چھین لیتاتھا.اس لئے میں سَفِيْنَةٍ غَصْبًا۰۰۸۰ نے چاہاکہ اسے عیب دار کردوں.تفسیر.اس آیت میں وہ تشریح بیان کی گئی ہے جوگزشتہ واقعات کی اس عبداللہ نے بیان کی ہے.بعض دفعہ خواب میں بتائی ہوئی تعبیر بھی تعبیر طلب ہوتی ہے اس کے متعلق یادرکھنا چاہیے کہ بعض دفعہ انسان خواب میں ہی تعبیرکر تاہے کبھی وہ تعبیر واضح ہوتی ہے اور کبھی وہ جزئی انکشاف کرتی ہے اوریقظہ کی حالت میں پھرایک دوسری تعبیر کی محتاج ہوتی ہے وہی معاملہ یہاں ہے جوتشریح عبداللہ نے کی ہے وہ کسی قدراغلاق کو ضرور دورکرتی ہے مگر واضح تعبیر نہیں بلکہ اس امر کی محتاج ہے کہ مادی دنیا کے اصول کے مطابق اس کی دوبارہ تشریح کی جائے.سب سے پہلے عبداللہ نے سفینہ والامعاملہ لیا ہے اوراس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ یہ کشتی مسکینوں کی تھی جواس سمند رمیں کام کرتے تھے پس میں نے چاہاکہ میںاس کو عیب دارکردوں اوراس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پرے ایک اوربادشاہ ہے جوہردرست کشتی کو جبراً چھین لیتا ہے پس اس بادشاہ کے ضررسے بچانے کے لے میں نے کشتی کوتوڑ دیا.مساکین کی تعبیر باقی سب امو ر کی تعبیر تومیں پہلے بتاآیاہوں صرف مسکینوںاوربادشاہ کی تعبیر باقی ہے.سومسکینوں کی تعبیر تو مسکین دل لوگ ہیں جن کو دنیا کے اموال اورترقیاں غریبوں کی خبرگیر ی اورا ن کی ہمدردی اوران کے ساتھ مل کررہنے سے نہیں روکتے.بادشاہ کی تعبیر اوربادشاہ سے مراد اس نظارہ میں دنیا پرستی کی روح ہے کیونکہ دنیوی بادشاہ دنیا کاایک ظہور ہوتے ہیں اور چونکہ جبراً کشتیاںچھین لینے کا ذکر ہے اس لئے اس سے مراد دنیا کی محبت کی روح ہے اورمراد یہ ہے کہ جن کی دنیا میں دینی روح نہیں ہوتی اورجن کے مالوں کاکافی حصہ غرباء اوررفاہ عامہ کے کاموں کے لئے نہیں نکلتا.ان کودنیا کی محبت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے.اوران کے مال شیطان کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں.اس لئے
Page 586
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے حکم سے اپنی امت کو حکم دیاہے کہ وہ اپنی سفینہ میں سوراخ کردیں یعنی ان کے مال دین کی خدمت اوربنی نوع انسان کی خدمت میں خرچ ہوتے رہیں تاکہ دنیا کی محبت ان کے دلوں پر قابو نہ پالے اوران کے اموال خداکے لئے ہونے کی بجائے ظالم دنیاکے لئے نہ ہوجائیں.آنحضرت ؐ کو دنیا ایک عورت کی شکل میں دکھائے جانے میں حکمت اس جگہ یہ لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواسراء میں دنیا ایک عورت کی شکل میں دکھائی گئی ہے.لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہی دنیا ا ن کےا سراء میں ایک ظالم بادشاہ کی شکل میںدکھائی گئی ہے.اس میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتاہے کہ دنیاکاحملہ امت محمدیہ پر بہت کمزورہوگا.اوروہ ایک بڑھیا کی طاقت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرے گی.لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اس کاحملہ شدیدہوگا اس لئے ان کی امت کو مدنظررکھتے ہوئے دنیا انہیں ایک ظالم بادشاہ کی شکل میں دکھائی گئی.وَ اَمَّا الْغُلٰمُ فَكَانَ اَبَوٰهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَاۤ اَنْ اوراس لڑکے (کے واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس )کے ماں باپ (دونوں)مومن تھے (اوروہ ایمان کادشمن تھا)اس يُّرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَّ كُفْرًاۚ۰۰۸۱ لئے ہم نے ناپسندکیا کہ وہ (اپنی )سرکشی اورکفر سے انہیں ایذاپہنچائے.تفسیر.میں اوپر بتاآیاہو ںکہغُلَامٌ کی تعبیر اَلْحَرَکَۃِ وَالْقُوَّۃِ وَالْجَہْلِ ہوتی ہے چنانچہ عبداللہ(یعنی اللہ کے بندے)نے جوتشریح فرمائی ہے وہ بھی اس کے مطابق ہے.وہ کہتے ہیں کہ غلام دونیک ماں باپ کابچہ تھا.پس ہم ڈرے کہ اگر اسے زندہ رہنے دیاگیاتووہ اپنے ماں باپ کے لئے سرکشی اورکفرکاموجب ہوگا.میں یہ توبتاچکاہوں کہ سرکش اولاد کوقتل کرنا بغیر کسی جرم کے ناجائزہے پس یہ نظارہ بھی تعبیر طلب ہے اورجب کہ غلام کی تعبیر حرکت قوۃ اورجہالت کی ہے تولازماً اس کے ماں باپ بھی اسی قسم کے ہونے چاہئیں کیونکہ حرکت قوت اورجہالت معنوی اشیاء ہیں مادی نہیں ہیں.جب ہم دیکھتے ہیں کہ حرکت قوت اورجہالت کہاں سے پیداہوتی ہیں توہمیں معلوم ہوتاہے کہ یہ اشیاء انسانی ر وح اور جسم سے پیداہوتی ہیں.اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم میں جوزوجین یعنی میاں اوربیوی کی حیثیت رکھتے ہیں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ مل کرانسان میں حرکت قوت اورجہالت یعنی
Page 587
عواقب سے بے پرواہوکرکام کرنے کی طاقت پیداکردیتے ہیں.لیکن یہ تینوں چیزیں جہاں انسان کی کامیابی کے لئے ضروری ہیں وہاںان کاحدود کے اندررکھنابھی ضروری ہے.اگران کوآزادچھو ڑدیاجائے توانسانی روح اور جسم طغیان او رکفرمیں مبتلاہوجاتے ہیں.کسی چیز کے جوش کو کم کردینا عربی زبان میں قتل کہلاتاہے.چنانچہ عربی کامحاورہ ہے قَتَلَ الشَّرابَ :مَزَّجَہٗ بِالْمَآءِ یعنی شراب میں پانی ملاکر اس کے جوش کوکم کردیا (اقرب) قَتَلَ الْجُوْ عَ وَالْبَرْدَوَنَحْوَذَالِکَ :کَسَّرَ شِدَّتَہٗ یعنی جب قَتَلَ الْجُوعَ وَالْبَرَدَ وغیر ہ الفاظ بولیں تومراد یہ ہوتی ہے کہ بھوک سردی وغیرہ کی تیزی کوکم کردیا (اقرب) قَتَلَ غَلِیْلَہُ: سَقَاہُ فَزَالَ غَلِیْلُہُ یعنے قَتَلَ غَلِیْلَہُ کے معنے ہیں اسے پانی پلاکر پیاس کو بجھادیا (اقرب)غرض قتل کالفظ صرف جاندارکے لئے ہی نہیں بولاجاتا.بلکہ جذبات اوراحساسات کے لئے بھی بولاجاتا ہے اوراس سے مراد ان جذبات اوراحساسات کی تیزی کو دور کرنا ہوتاہے.عبداللہ کی تاویل کا مطلب پس عبداللہ کی تاویل کایہ مطلب ہواکہ حرکت قوت اورجہالت کے ماں باپ تومومن ہیں یعنی ان میں احکام الٰہی کے ماننے کامادہ ہے ان کو اعلیٰ سے اعلی اعما ل کی قوت بخشی گئی ہے اوران قوتوں کوعمل میں لانے کے لئے حرکت قوت اورجہالت کی طاقتیں ان میں سے پیداکی گئی ہیں.یعنی ایک توروح اوردماغ انسانی میں آگے بڑھنے کاشدید مادہ ہے دوسرے بڑے بڑے کام کرنے کی طاقت ہے تیسرے بڑے بڑے خطرات برداشت کرنے کی ہمت ہے ان تینوںقوتوں سے جوروح اور جسم کے امتزاج سے انسان میں پیداہوتی ہیں وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرسکتاہے.لیکن اگران قوتوں کو بے لگام چھوڑ دیاجائے تویہی قوتیں انسانی روح اورانسانی جسم کو نافرمانی اورکفرکی طرف لے جاتی ہیں اوروہ ہلاک ہو جاتا ہے.پس اللہ تعالیٰ نے پسند نہ فرمایا کہ انسانی روح اورانسانی جسم جیسے اعلی اورکارآمد وجودوں کو طغیانی اورکفر میں مبتلاہونے دے.پس اس نے جلوئہ محمدی کے ذریعہ سے ان تین طاقتوں کوقتل کروادیا.یعنی شریعت کے احکام کے ذریعہ سے ان کوسمودیا اوران کی شدت کوکم کردیاتاکہ اس کے بعد جوجذبات انسان میں کام کریں وہ نیکی کی قیو دکے ماتحت اوراس کے حلقہ میں کام کریں.
Page 588
فَاَرَدْنَاۤ اَنْ يُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّ اَقْرَبَ اس لئے ہم نے چاہاکہ ان کارب انہیں پاکیز گی میں ان سے اچھا اوررحم(وشفقت)میں (اپنے ماں باپ رُحْمًا۰۰۸۲ سے)زیادہ قریب (لڑکا)بدل دے.تفسیر.یعنی یہ قیود اورپابندیاں اس لئے لگائی گئیں تاکہ انسان کے اندر آزاد جذبات کی بجائے پابند اخلاق جذبات پیداہوں گویاپہلے جذبات قتل ہوکر ایک نیا صالح بیٹا ان کوملے جوانسان کامطیع ہو اوربجائے اس کو کفرو طغیان کے گڑھے میں گرانے کے اس کورحمت الٰہی کامستحق بنائے.زَكٰوةًکے معنی زَكٰوةًکے معنے پاکیزگی اورترقی کے ہوتے ہیں.اور رحم کے معنے رقت اورتلطّف کے ہوتے ہیں (اقرب).پس معنے یہ ہوئے کہ جونیابیٹاہوگا وہ ان کی ترقی اورپاکیزگی کاموجب اوران کی باتیں ماننے والا اوران کی اطاعت کرنے والاہوگا یعنے جب آزاد قوائے انسانی کو شریعت کی تلوار سے قتل کردیاجائے گا.اوران کی وحشیانہ آزادی کی شدت کوتوڑ دیاجائے گاتووہ ایسی شکل اختیارکرلیں گے کہ روح و جسم کی بات مانیں گے اوران کی ترقی اورپاکیزگی کاموجب ہوں گے.مگرجیساکہ بتایاجاچکاہے موسوی قو م نے ا س نکتہ کو نہ سمجھا اورعیش پرستی اوربے پردگی اورلہوولعب میں مشغول ہو گئے.جس کی وجہ سے ان کی حرکات میں تیزی ان کی قوتوں میں حدت اوران کی بے باکانہ جرأت میں ایک شان توضرورنظر آتی ہے لیکن یہ طاقتیں انہیں طغیان وکفرمیں بڑھارہی ہیں اورنیکی اورتقویٰ سے دورکررہی ہیںاور مذہب و عقل جوروح اور جسم کے نمائندے ہیں ان کی بات ماننے کے لئے جذبات تیارنہیں ہوتے.وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِيْنَةِ وَ اوروہ دیوار اس شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اورا س کے نیچے ان کا کچھ خزانہ (گڑاہوا)تھا.اوران کاباپ نیک كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا١ۚ فَاَرَادَ (اورمناسب حال کام کرنے والا )تھا.اس لئے تیرے رب نےچاہا.کہ وہ اپنی مضبوطی کی عمرکوپہنچ جائیں
Page 589
رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا١ۖۗ رَحْمَةً اور(بڑےہوکر)اپناخزانہ(خود)نکالیں.تیرے رب کی طرف سے (ان پر خاص )رحم (ہوا)ہے اور مِّنْ رَّبِّكَ١ۚ وَ مَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِيْ١ؕ ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا یہ (کام )میںنے اپنے نفس کے حکم سے نہیں کیا.یہ اس بات کی حقیقت ہے لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا۰۰۸۳ جس پرتوصبر نہیں کرسکا.حلّ لُغَات.الکنزُ اَلْکَنْزُکے معنے ہیں اَلْمَالُ اَلْمَدْفُوْنُ فِی الْاَرْضِ.دفینہ.وَقِیْلَ اِسْمٌ لِلْمَالِ اِذَااَحْرَزَفِی وِعَاءٍ اوربعض اس مال کوکہتے ہیں جو تھیلے وغیرہ میں محفوظ رکھاجائے.اَلذَّھَبُ.سونا.اَلْفِضّۃُ.چاندی (اقرب) تاویل تَأْوِیْلٌ کے معنوں کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۴۰.اَلتَّأْوِیْلُ:اَلظَّنُّ بِاِلْمُرَادِ.کسی کلام کے مطلب و مدعا کی نسبت ظن غالب بَیَانُ اَحَدِ مُحْتَمَلَاتِ اللَّفْظِ کسی لفظ کے کئی احتمالی معانی میں سے کسی ایک کی تعیین کرنا.اَلْعَاقِبَۃُ انجام.اَوَّلُ الشَّیْءَ: رَجَّعَہُ لو ٹایا.اَلْکَلَامَ دَبَّرَہُ وَ قَدَّرَہُ وَفَسَّرَہُ تدبر کیا اور اس کا صحیح مطلب نکالا.الرُّؤْیَا: عَبَّرَھَا تعبیر کی.(اقرب) تفسیر.یعنی اب ایک سوال حل طلب رہ گیا ہے جس میں ہماراتمہارااختلاف ہے اوروہ یہ کہ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ بغیر کسی ذاتی غرض کے ہم نے ایک گرتی ہوئی دیوار کس طرح بنادی.سواس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار ایک خزانہ کی محافظ تھی اوریہ خزانہ دویتیموں کاتھا جن کاباپ صالح تھا.پرانی دیوار سے مراد یہود و نصاریٰ کے بزرگ جیساکہ میں بتاچکا ہوں دیوارسے مراد یہود ونصاریٰ کے بزرگ ہیں یعنی خود موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام اوران کے باپ حضرت ابراہیمؑ ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِنَّہٗ فِی الْاٰخِرَۃِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ(النحل :۱۲۳)اورکنز سے مراد وہ علمی خزانہ ہے جسے موسیٰ اورعیسٰی علیہماالسلام کی تعلیم نے محفوظ کیا ہواتھا.مگریہود ونصاریٰ کی بے توجہی اوردین سے دوری کی وجہ سے موسیٰ اورعیسٰی علیہما السلام کاتصرف جوان خزانوں کی حفاظت کے لئے کام کررہاتھا کمزورپڑ گیاتھا.محمد رسول اللہ صلعم نے پھر اس دیوار کوبنادیایعنے ایک نئے
Page 591
ممنون نہ تھے استقبال کے لئے آئے جس کے یہ معنی تھے کہ ہم نے پہلے آپ کی اس خدمت کو براسمجھاتھا مگراب اللہ تعالیٰ نے ہم پر حقیقت کھول دی ہے اس لئے اے محمدؐ آپ پر سلام ہو آیئے ہمارے گھروں کو برکت دیجئے.اورہماری امتوں کونجات دلائیے.ا ب دیکھو کہ یہ مضمو ن جو علم تعبیرالرویا سے نکلتاہے یہ توایساضروری ہے کہ اس کے لئے رسول کریم صلعم فرماتے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے توامت محمدیہ اور میرے کاموں کی کچھ اورتفصیل ہمیں ان کے اسراء سے معلوم ہوجاتی(بخاری کتاب التفسیر سورۃ الکہف قولہ تعالیٰ واذ قال موسیٰ...).مگرکون عقلمند کہہ سکتاہے کہ محمد رسول اللہ صلعم نے یہ فرمایاکہ یہ سینما کچھ دیراورہوتا توہم بھی کشتیوں کے ٹوٹنے نوجوانوں کے قتل ہونے اوردیواروں کے تعمیرکانظارہ دیکھتے.نعوذ باللہ من ذالک.وَالْـحَمْدُ لِلہِ الَّذِیْ وَ ھَبَ لِی مِنْ لَّدُنْہُ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا وَاِسْلَامًا.آمین اسراء موسیٰ میںبیان کردہ امور کی حکمت اسراء موسیٰ ان واقعات اوران تشریحا ت کوپڑھ لینے کے بعد جومیں نے اوپربیان کی ہیں یہ آسانی سے سمجھ میں آسکتاہے کہ موسیٰ کے اسراء کو اس جگہ پر اس لئے بیان کیاگیاہے تایہ بتایاجائے کہ(۱)حضرت مسیح ناصری کی قوم جوامت موسویہ کاآخر ی حصہ ہے اس کے بگڑ جانے کے بعد بعثت محمدیہ مقدر تھی.(۲)پس جب دورتوحید کے بعد مسیحی بگڑ گئے تومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاظہور ضروری تھا.(۳)اسلام کی تعلیم ایسے قوانین اورایسے اصول پر مبنی ہے کہ موسوی تعلیم اس سے بعض جگہ شدید اختلارف رکھتی ہے.اس وجہ سے موسوی اورعیسوی امتوں کے لئے اس کے ساتھ تعاون کرنا مشکل ہے مگراس تعلیم کے بغیرنجات بھی نہیں.(۴)یہودی اور مسیحی لوگ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوان کے دعویٰ کے وقوت نہیں مانیں گے بلکہ بحیثیت قوم ایک لمبے عرصہ کے بعد مانیں گے.اس عرصہ میں وہ اپناروحانی سفرالگ طور پر جاری رکھیں گے (۵)آخر ایک لمبے عرصہ کے بعدوہ تھک جائیں گے اوران کے دل اپنی کوششوں کے ذریعہ امن حاصل کرنے سے مایو س ہوجائیں گے تب و ہ اپنی حالت کاجائز ہ لیں گے اورسمجھ لیں گے کہ یہ سفرہم نے بغیرکسی مقصد کے جاری رکھا.درحقیقت ہمارااکیلا سفر بہت پیچھے ختم ہوچکا ہے.(۶)اس وقت وہ پیشگوئیاںجوقرآن کریم نے ان کی کتب سے محفوظ کرلی ہیں ان کی ہدایت کاموجب ہوں گی اور(۷)وہ ان قیود کوتسلیم کرنے کے لئے تیار ہوجائیں گے جن کوماننے کے لئے تیار نہ تھے.اوراپنے وحشی جذبات کوقتل کرکے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار جذبات پیداکرنے پر آمادہ ہوجائیں گے تب اللہ تعالیٰ کارحم ان پرنازل ہوگا اوروہ اس کی رحمت کے سمندر میں داخل ہوجائیں گے جس کاکوئی کنارہ نہیں جس کے بعد کوئی اورسمندر نہیں.سوائے اس کے جواس کاحصہ ہو اوراسی میں سے ہو.
Page 592
وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ١ؕ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ اوروہ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں تو(انہیں )کہہ (کہ)میں ضروراس کے متعلق کچھ ذِكْرًاؕ۰۰۸۴ ذکرتمہارے سامنے کروں گا.حلّ لُغَات.اَلْقَرْنَیْنِ اَلْقَرْنُ کاتثنیہ ہے اوراَلْقَرْنُ کے معنے ہیں.اَلرَّوْقُ مِنَ الْحَیَوانِ.جانورکاسینگ.اَلْقَرْنُ :مِائَۃُ سَنَۃٍ.سوسال.اَلْقَرْنَانِ کَنَایَۃٌ عَنْ مَشْرِقِ الْاَرْضِ وَمَغْرِبِھَا یعنی قرنان کالفظ بول کر کنایۃً مشرق اورمغرب کے ممالک مرادلیتے ہیں(اقرب) تفسیر.ذوالقرنین کے واقعہ کی طرف راہنمائی کا فخر حضرت خلیفۃ المسیح اولؓ کو یہ ذوالقرنین کاواقعہ بھی ایساہے کہ خدا تعالیٰ نے استاذی المکرم حضرت مولوی نورالدین صاحب ؓکواس کی طرف راہنمائی کرنے کافخر بخشا ہے.اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے مضمون پرزمانہ حال کے بعض دوسرے مصنفوں نے بھی روشنی ڈالی ہے اوراس غلط خیال کی تردید کی ہے کہ اس سے مراد سکندررومی ہے.اوربعض نے ذوالقرنین کے یہ معنے کئے ہیں کہ ایک باد شاہ جس کی حکومت مشرقی اورمغربی ممالک میں پھیل گئی تھی.بلکہ ایک جرمن ڈاکٹر ہربیلاٹ مصنف ببلیااورئینٹل نے تویہ کہہ کر کہ اس سے مراد ایران کے ابتدائی بادشاہوں میں سے کو ئی ہے قریباً صداقت پرہاتھ جاماراہے.(ویریز کمنٹری آن قرآن )حضرت مولوی صاحب نے ذوالقرنین کے بارہ میں اپنی تحقیق کی بنیاد بائبل پررکھی ہے.آپ فرماتے ہیں.دانیا ل نبی کی ایک خواب بائبل میں لکھی ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رویا میں ایک مینڈھا دیکھا جس کے دوسینگ تھے.اوروہ پچھم اتردکن کی طرف سینگ مارتاتھا اورکوئی جانوراس کے سامنے نہ ٹھہر سکتاتھا اوروہ جوچاہتاتھا کرتاتھا.(دانیال باب ۸ آیت۳،۴)پھر لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ’’وہ مینڈھا جسے تو نے دیکھا کہ اس کے دوسینگ ہیں سوو ہ مادہ اورفارس کے باد شاہ ہیں ‘‘(باب۸ آیت۲۰) اس خواب کی بناء پر جس میں ماد ہ اورفارس کے بادشاہوں کودوسینگ والے مینڈھے کی شکل میں دکھایا گیاہے آپ فرماتے تھے کہ ذوالقرنین سے مراد ماد ہ اورفارس کاکوئی باد شا ہ ہے.نیز آپ کایہ بھی خیال تھا کہ یہ بادشاہ کیقباد
Page 593
تھا (فصل الخطاب صفحہ ۲۰۷،۲۰۸).ذوالقرنین کاواقعہ بیا ن کرنے کی حکمت حضرت استاذی المکرم کا خیال بیان کرنے کے بعد اب میں اپنی تحقیق بیان کرتاہوں.مگرپیشتراس کے کہ میں ذوالقرنین کے متعلق اپنی تحقیق بیا ن کروں میں یہ امر بیان کرناچاہتاہوں کہ ذوالقرنین کاواقعہ قرآن کریم میں کیوں بیان کیا گیا ہے اوراسے سورۃ کہف کے اس حصہ میںواقعہ اسراء کے بعد کیوں رکھا گیاہے.میں اوپربیان کرآیاہوں کہ سورۃ کہف میں اسلام اور مسیحیت کے مقابلہ کا ذکر ہے خصوصاً ا س حصہ کامقابلہ جونیم سیاسی کہلاسکتاہے یعنی ہے تومذہبی مگردونوں مذہبوں کی سیاسیات سے وابستہ ہے.سورۃ کہف کے واقعات کی ترتیب حکمت کے ماتحت ہے سب سے پہلے اصحاب کہف کاواقعہ بیان کرکے بتایا کہ مسیحیت کی ابتداء کس طرح ہوئی اوروہ کس طرح بگڑے پھرموسیٰ علیہ السلام کے اسراء کے واقعہ کوبیان کرکے بتایا کہ اصحاب کہف کی نسلوں کی ترقی ایک حد تک جاکر رک گئی.کیونکہ موسیٰ کے اسراء میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ موسیٰ ؑ کی قوم ایک حد تک جاکر روحانی ترقی سے محروم ہوجائے گی اوراس وقت ایک او رنبی خدا تعالیٰ کی طر ف سے ظاہرہوگا اوریہ بھی بتایاگیاتھا.کہ موسیٰ کی قوم سے مراد اس جگہ موسوی سلسلہ کاآخری حصہ ہے یعنی مسیحی.ورنہ خالص موسوی حصہ توپہلے ہی مردہ ہوچکا ہے.غرض اصحاب کہف کے واقعہ کے بعد اسرا ء موسیٰ کاواقعہ بیا ن کرکے بتایا کہ مسیحی قوم کی پہلی ترقی کادورمحمد رسول اللہ صلعم کی بعثت کے ساتھ ختم ہوجائے گا.چنانچہ بعدکے واقعات سے یہ پیشگوئی زبردست طورپرپوری ہوئی اورمومنوں کے ایما ن کو اس سے بے انتہاتقویت ملی.کیونکہ مکی زندگی میں یہ خبر دینا کہ مسلما ن عیسائیوں کو زک دیں گے ایک ایسی زبردست پیشگوئی ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی.اس کے بعد ذوالقرنین کاواقعہ مسیحی قوم کے ترقی کے دوسرے دور کی خبردینے کے لئے بیان کیاگیاہے.اگر کہا جائے کہ اس طریق کواختیار کرنے کی کیاضرورت تھی معمولی طور پر مسیحیت کی ساری ترقی کواکٹھابیان کردیاجاتا.تواس کایہ جواب ہے کہ دنیاداروں کی نگاہ میں بے شک یہ معمولی بات ہے لیکن جو شخص دین کی اہمیت کو سمجھتاہووہ اسے کسی صورت میں جائز نہیں کہے گا.بلکہ قرآن کریم کے اختیار کئے ہوئے طریق کو ہی درست اورضروری قراردے گا.اقوام کی مذہبی اقسام تفصیل اس اجما ل کی یہ ہے کہ الٰہی قانون کے مطابق جوشروع زمانہ سے چلا آیاہے اقوام کی مذہبی حالت چا رقسم کی ہوتی ہے (۱)وہ قومیں جو نبی وقت پرایما ن لاتی ہیں اوراس ایما ن پر ثابت قدم رہتے
Page 594
ہوئے دینی دنیوی ترقیا ت حاصل کرتی ہیں (۲) و ہ قو میں جونبی وقت پر ایما ن لاتی ہیں لیکن بدکاریوں اورشرارتوں میں مبتلاہوجاتی ہیں.یہ قومیں گواللہ تعالیٰ کے غضب کے نیچے ہوتی ہیں لیکن اپنی قومی ہیئت تبدیل کئے بغیر اسی مذہب میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کرکے خدا تعالیٰ کے فضل کودوبار ہ جذب کرسکتی ہیں کیونکہ نبی وقت پر انہیں ایمان ہوتاہے صرف عمل خراب ہوتے ہیں(۳)و ہ قومیں جو نہ صرف بدعمل ہوجاتی ہیںبلکہ ان کی خرابی کے زمانہ میں دوسرانبی آجاتاہے اوروہ اس کے ماننے سے محروم رہ جاتی ہیں.اس وقت ان کی طرف سے کسی قسم کی اصلاح کی کوشش بھی خدا تعالیٰ کوراضی نہیں کرسکتی جب تک کہ وہ اپنی قومی ہیئت کو نہ بدلیں.اوراللہ تعالیٰ کے آخر ی نبی کوقبول نہ کریں.(۴)و ہ قومیں جو کسی نبی پر ایما ن ہی نہیں رکھتیں اوران کی سب ترقیات خالص دنیو ی ہوتی ہیں.اور خدا تعالیٰ سے روحانی تعلق پیداکرنے کے لئے ضروری ہوتاہے کہ وہ وقت کے نبی پر ایما ن لاکر اس کے احکام کے مطابق عمل کر یں.ان چاروں حالتوں کے سمجھ لینے کے بعد یہ امر آسانی سے سمجھ میں آسکتاہے کہ مسیحی ترقی کے دوراول کا آخر ی حصہ اس قوم کودوسری قسم کی اقوام میں شامل کرتاہے یعنی اس وقت و ہ دین سے دور توجاچکے تھے.مگراپنی ہیئت بدلے بغیر اللہ تعالیٰ سے صلح کرسکتے تھے کیونکہ وہ حضرت مسیح کوجووقت کے نبی تھے مانتے تھے.مگراس کے بعد اسراء موسیٰ کی پیشگوئی کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوگئے.اورا ب مسیحی قسم دوم سے نکل کر قسم سوم میں شامل ہوگئے.کیونکہ وہ مجمع البحرین کو بھول کر آگے نکل گئے یعنی ان کی عملی اوراعتقادی حالت ہی خراب نہ رہی بلکہ خدا تعالیٰ سے صلح کرنے کے لئے اب ضروری ہوگیا کہ وہ اپنی سیاست اوراپنے نظام کوبھی ترک کریں اورمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرایما ن لا کر اسلامی نظام اوراسلامی سیاست میں شریک ہوجائیں.ظاہر ہے کہ جب یہ دونوں قسمیں اس قدر مختلف ہوں اورخصوصاً جبکہ گفتگونیم سیاسی اثرات کے متعلق ہوتواس عظیم الشان فرق کونظرانداز نہیں کیاجاسکتا اورجبکہ ا س طریق کلام سے مزید فائدہ یہ پہنچتاتھا کہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاوجودمسیحی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تویہ ترتیب نہ صرف ضرور ی معلوم ہوتی ہے بلکہ ایک معجزانہ ترتیب معلوم ہوتی ہے.خلاصہ یہ کہ پہلے اصحاب کہف کا ذکرکیا گیا ہے جبکہ مسیحی یاتونیک تھے یا بگڑ چکے تھے مگرنبی وقت کے ماننے والے تھے اورخدا تعالیٰ سے صلح کرنے کے لئے انہیں اپنی قوم اوراپنی سیاست کوچھوڑنے کی ضرورت نہ تھی.اس کے بعد موسیٰ کی زبانی محمد رسول اللہ ؐ کے ظہورکی خبر دی اوربتایاکہ اس نبی کے پیدا ہونے کے بعد مسیحی قوم کی حالت
Page 595
بدل جائے گی.انہیں پھر بھی ترقی توملے گی لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے صلح کرنی ناممکن ہوگی کیونکہ وقت کے نبی کوپیچھے چھوڑ کر وہ آگے نکل چکے ہو ں گے.جب تک وہ واپس آکر اس نبی کے ہمرکاب نہ ہوں گے ان کی ترقیات خالص دنیو ی ہوں گی اورآخرت کااس میں کوئی بھی حصہ نہ ہوگا.پس اس زمانہ کاحال الگ بیان کیاکیونکہ اس زمانہ کی مسیحی قو م نہ صرف سیاستاً بلکہ مذہباًبھی پہلے مسیحیوں سے جداگانہ حیثیت رکھتی ہے.مسیحی ترقی کے دو۲ دوروں کا ذکر آسمانی کتب میں یہاں ایک اوربات قابل تشریح ر ہ جاتی ہے اورو ہ یہ کہ ذوالقرنین کا ذکربیچ میں کیوں کیا.جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کاتھا.سواس کا جواب یہ ہے کہ مسیحی ترقی کے دو۲ دوروںکانام آسمانی کتب میں الگ الگ رکھا گیا ہے.ایک دوراصحاب کہف کادورہے.یعنی جبکہ اصحاب کہف والی کیفیت ان میں پیداتھی.یا وہ اصحاب کہف کی طرح نیک بننے کی قابلیت رکھتے تھے گو عملاً نیک نہ ہوں.دوسرادورآسمانی کتابوں میں دور یاجوج ماجو ج کہلاتاہے یعنی وہ دور جس میں نیک بننے کی قابلیت ہی ان سے جاتی رہے گی اورایک نئے نبی کے ظہور کی وجہ سے وہ اپنی ہیئت قومی چھو ڑکرہی خدا تعالیٰ کو پاسکیں گے.اس نئے دورکے ساتھ ذوالقرنین کا تعلق ہے اورذوالقرنین کے بعض اعمال اس دور کے پیدا ہونے کاموجب ہوئے ہیں.یاجوج ماجوج اقوام کی تشریح اوروہ اس طرح کہ یاجوج وماجوج ان قومو ں کانام ہے جو شمالی ایشیا اورمشرقی یورپ کے علاقوں میں رہتی تھیں.ایشیا کی زرخیزی کی وجہ سے وہ اس پر حملے کرتی تھیں(جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Clog and Mogog).اگران حملوں میں وہ کامیا ب ہوجاتیں توجس طرح آریہ قوم ہندوستان میں بس کر دوسری پرانی قوموں میں مل جل گئی ہے یہ قومیں بھی ایشیا کے مختلف ممالک میں پھیل کردوسری اقوام کے ساتھ مل جاتیں اورہرملک کے مطابق مذاہب اختیا رکرلیتیں اور کسی ایک مذہب پر جمع نہ ہوتیں.لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت سے ہوایہ کہ ذوالقرنین (جس کے متعلق تفصیل آگے آئے گی)نے ان اقوام کے حملو ں کو بڑی سختی سے روک دیا.اوریہ اقوام ایشیاکے انتہائی شمال مغرب اوریوروپ کے مشرق میں گھر گئیں اورذوالقرنین نے اس امر کاانتظام کیا کہ ان اقوا م کے ایشیا میں آنے کی صورت ہی نہ رہے اورگویا ایک قسم کابائیکاٹ کردیاگیا.نتیجہ یہ ہواکہ یہ اقوام یورپ میں پھیلنی شروع ہوئیں.اور چونکہ یو رپ میں مذاہب میں سے صرف مسیحی مذہب تھا باقی بت پرستی ہی بت پرستی تھی.اس لئے دنیا کے پرانے مذاہب میں سے ان اقوام کو صرف مسیحیت سے واسطہ پڑا اوریہ اقوام آہستہ آہستہ سب کی سب مسیحی ہوگئیں اورساری قومیں ایک ہی مذہب میں شامل ہوکر دوسری دنیا کے مقابلہ میں ایک زبردست جتھابن گئیں.اس طرح مذہبی عداوت کابیج بویاگیا.اس کے علاوہ چونکہ ذوالقرنین کے ماتحت اوراس کی پالیسی پر عمل کرکے سب ایشیا
Page 596
نے ان کو شمال کی طرف دھکیل دیا جوا س زمانہ کے لحاظ سے سب سے ردّی اورسب سے حقیر علاقہ تھا.ان قوموں کے اندر ایشیا اورمشرق کی طرف آنے کی ایک زبردست خواہش پیداہوگئی جواپنی شدت کی وجہ سے ہرنسل سے دوسری نسل کی طرف وراثتہً منتقل ہوتی چلی گئی او راس طرح سیاسی عداوت کابیج بویاگیا.غرض ذوالقرنین ایک لحاظ سے یاجوج ماجوج یادجالی فتنہ کے پیداکرنے کاموجب ہوا.پس اللہ تعالیٰ نے مسیحی ترقی کے اس دور کا ذکر کرنے سے پہلے ذوالقرنین کا ذکر کیااورخصوصاً اس کے اس فعل کا جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی ایک علیحدہ قو می اورسیاسی بنیاد پڑی.ذوالقرنین فارسی الاصل تھا ذوالقرنین کے ذکر میں ایک اورحکمت بھی ہے.اوروہ یہ کہ ذوالقرنین مادہ اور فارس کابادشاہ تھا.پس اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی پیدائش ایک فارسی نسل کے انسان کے ذریعہ سے ہوئی.اوراللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو اس کے نیک بندے ہو ںجب ان کے کسی نیک فعل کے ثانوی ردعمل کے طور پر کوئی بدی پیداہو تووہ انہی کی اولاد یاہم وطن یا مثل کے ذریعہ سے اس بدی کودورکرواتاہے کہ اس کے نیک بندے کے نام سے ایک دورکا عیب بھی منسوب نہ ہو.حضرت مسیح موعود اور ذوالقرنین کے فارسی الاصل ہونے میں مشابہت پس ذوالقرنین کا ذکر اس جگہ اس لئے کیا گیا.تااس خبرکوبطورپیشگوئی بیان کرکے ایک دوسرے ذوالقرنین کی خبر دی جاسکے جوفارسی الاصل ہوگا اور یاجوج ماجو ج کامقابلہ کرکے اس کے زورکوتوڑے گااور اس طرح پہلے ذوالقرنین پر سے الزام کودور کر ے گا اور ذوالقرنین کانام اس وجہ سے پائےگا.کہ اللہ تعالیٰ اسے دوقوتوں کاوارث بنائے گا.ایک مہدویت کی قوت اورایک مسیحیت کی قوت.وہ محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کاوارث ہونے کی وجہ سے مہدی کہلائے گا اور حضرت مسیح ؑ کی صفات کو اخذ کرنے کی وجہ مسیح کہلائے گا.جیساکہ حدیثوں میں ہے کہ لَامَھْدِیَّ اِلَّا عِیْسٰی.پس ان دونوں قوتوں کے حاصل ہونے کے سبب اس کانا م ذوالقرنین ہو گا.نیزاس وجہ سے بھی کہ و ہ بعض پیشگوئیوں کے مطابق دوصدیوںکو پائے گا.یعنی ایک صدی کے خاتمہ پروہ خدا تعالیٰ سے الہام پائے گااوردوسری صد ی کے شروع ہونے پر اپناکام ختم کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایاجائے گا.اسی کی طرف حدیث ابن ماجہ میں اشارہ ہے کہ لَامَھدی اِلَّاعِیْسٰی (باب شدۃ الزمان)یعنی آنے والاموعود ذوالقرنین ہو گا من جہت مہدی اورمن جہت عیسیٰ ہوگا.احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا کہ یارسول اللہ یہ جوقرآن کریم میں آتاہے کہ ایک اورجماعت بھی ہو گی جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر قرآن پڑھائیں گے اس
Page 597
سے کیا مراد ہے.یعنی اگرآپ فوت ہوچکے ہو ں گے تویہ کام کس طرح کریں گے اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسیؓ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ فرمایا کہ وَالَّذِیْ نَفْسِی بِیَدِہٖ لَوْکَانَ الْاِیْمَانُ بِالثُّریَّا لَنَالَہُ رِجالٌ مِنْ ھٰٓؤُلَآءِ(الدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور سورۃ الجمعۃ زیر آیت وآخرین منھم لما...) اور ابن مردویہ نے سعد ابن عباد ہ سے جوروایت کی ہے.اس میں لکھا ہے رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ کہ فارسی لوگ ایما ن کو پھرواپس لے آئیں گے.اوربعض روایات میں رجُلٌ کالفظ بھی آتاہے (بخاری)یعنی ایک خاص موعود کی طرف اشارہ کیا گیاہے.ان سب روایات کو ملاکر معلوم ہوتاہے کہ ایک خاص موعود شخص جو فارسی الاصل ہوگاآخری زمانہ میں ایمان کے اٹھ جانے کے بعد پھر ایما ن کوواپس لائے گا.اوراس کے اس کام میں بعض اورفارسی الاصل لوگ بھی اس کے مؤیدہوںگے.اب رہایہ سوال کہ اس کا یاجوج ماجوج کے زمانہ سے کیاتعلق ہے ؟ یاجوج ماجوج، دجال ایک ہی مذہب والوں کے نام ہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم اوراحادیث سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ اسلام کی یہ حالت آخری زمانہ میں ہوگی جبکہ یاجوج ماجوج اوردجال کا ظہور ہوگا اوریہ بھی معلوم ہوتاہے کہ دونوں نام ایک ہی مذہب والوں کے ہیں.فرق یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کالفظ سیاسی فتنہ پردلالت کرتاہے اوردجال کامذہبی فتنہ پر.پس دونوں قسم کی روایات کوملاکریہ حقیقت ظاہرہوجاتی ہے کہ یاجوج ماجوج کے زمانہ میں جواشاعت کفر ہوگی اس کامقابلہ ایک فارسی مردکرے گا.اوراس کے اس کام میں معاون بعض اورفارسی مرد بھی ہوں گے.پس فارسی الاصل ذوالقرنین کے فعل پر جواعتراض پڑتاتھا.اس کابھی اس کے تفصیلی حالات بیان کرکے ازالہ کردیا اوراس واقعہ کو قرآن کریم میں بطورپیشگوئی کے بیان کرکے یہ بھی بتادیا کہ اگر ایک ذوالقرنین نے دنیوی طور پر یاجوج ماجوج کے حملوں کی روک تھام کی تھی تو ایک اورذوالقرنین ان کے مذہبی حملوں کی جوآئندہ زمانہ میں ہونے والے ہیں روک تھام کرے گا.ذوالقرنین پر بھی اعتراض ہوا کہ فارسی الاصل نہیں (صاحبان ذوق کے لئے یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس طرح دوسرے ذوالقرنین پر اعتراض کیاگیاہے کہ یہ اصل میں فارسی الاصل نہیں کیونکہ اس کے آباء فارسی ہونے سے پہلے چینی علاقہ کے رہنے والے تھے.اسی طرح ذوالقرنین اول کی نسبت تاریخ میں آتاہے کہ وہ اصل میں ماد ہ کاتھا فارسی صرف عارضی تعلقات کی وجہ سے کہلاتاہے ) رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ کی صفات بہاء اللہ میں نہیں پائی جاتیں میں اس جگہ ایک اورشبہ کاازالہ بھی کردینا چاہتاہوں کہ بعض بہائی لوگ ان پیشگوئیوں کوبہاء اللہ پر چسپاں کرتے ہیں کہ وہ فارسی الاصل تھے.مگریہ
Page 598
درست نہیں.کیونکہ احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ جس موعود کا ذکر ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم دے گااورمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانائب ہوگا.کیونکہ سورئہ جمعہ کی جس آیت کے متعلق آپؐ نے جو کچھ فرمایا.اس کاتومضمو ن ہی یہ ہے کہ ایک دفعہ تواب قرآن کی تعلیم محمد رسول اللہ صلعم نے عربوں کو دی ہے اورایک دفعہ پھر وہ ایک اورقوم کو جوابھی تک پیدا نہیں ہوئی یہی تعلیم دیں گے.پس وہی شخص ا س پیشگوئی کو پوراکرنے والا ہو سکتا ہے جو (۱)فارسی الاصل ہو (۲)دوسرے محمد رسول اللہ کے شاگردہونے کامدعی اورقرآن کریم کی تعلیم دینے والاہو (۳)آیات قرآنیہ کوساتھ ملالیا جائے تویہ شرطیں بھی شامل کرنی پڑیں گی کہ وہ ذوالقرنین ہو یعنی دوصدیوں کوپانے والاہو (۴)وہ یاجوج ماجوج کے فتنہ کو جس کاجزواعظم بندوں کو خدائی صفات دینا ہے تباہ کرے.ان میں سے فارسی الاصل ہونے کے سوا کوئی بات بہاء اللہ میں نہیں پائی جاتی.نہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں نہ قرآن کی طرف لوگوں کوبلاتے ہیں نہ انہوں نے دوصدیاں پائیںاورنہ انہوں نے یاجوج ماجوج کے فتنہ کوتوڑابلکہ انہوں نے تواپنے آپ کو خداکہہ کے اس فتنہ کی آگ میں تیل چھڑکاہے اوراسے اوربھی بھڑکادیاہے.ذوالقرنین کے متعلق اپنی تحقیق ان تمہیدوں اورترتیب مضمو ن کوبیا ن کرنے کے بعد اب میں ذوالقرنین کے متعلق اپنی تحقیق بیان کرتاہوں.میں اوپربتاچکاہوں کہ جیساکہ سابق مفسروں اوریورپین محققین کاخیا ل ہے اورجیسا کہ حضرت مولو ی نور الدین صاحبؓ خلیفہ او ل جماعت احمد یہ نے بیان کیا ہے.میرے نزدیک بھی ذوالقرنین ایرانی باد شاہوں میں سے کسی ایک باد شاہ کانا م ہے.حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ اس کانام کیقباد بتاتے تھے.ذوالقرنین کی علامات قرآن کریم سے بعض نے آپ کی تحقیق میں یہ فرق کردیا ہے کہ اس بادشاہ کودارائے اول قرار دیا ہے (بیان القرآن زیر آیت ھذا).مگرمیرے نزدیک ہمیں سب سے اول ان شرائط کودیکھنا چاہیے کہ جوقرآن کریم میں بیا ن ہوئی ہیں اورپھر اس بادشاہ کی تعیین کرنی چاہیے.قرآن کریم سے معلو م ہوتاہے کہ (۱)ذوالقرنین کو الہا م یا خوابیں آتی تھیں (۲)وہ اپنے علاقہ سے توملک فتح کرتے ہوئے مغرب کی طرف چلا گیا جہاں ایک سیاہ چشمہ میں سورج ڈوب رہاتھا (۳)اس کے بعد و ہ مشرق کی طرف متوجہ ہوااورمشرقی ممالک کوفتح کیا (۴)پھر وہ ایک درمیانی علاقہ کی طرف گیا.جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ کررہے تھے اورا س نے وہاں دیوا ربنائی.ہمیں ذوالقرنین کی تعیین کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جوشخص ہمارے ذہن میں مشارٌ الیہ
Page 599
ذوالقرنین کہلانے کامستحق ہے اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں یانہیں.خصوصاً ا س امر کو کہ وہ صاحب الہام اور خدا تعالیٰ کامقبول بھی ہے یا نہیں.یہ امرتوپہلے طے ہوچکا ہے کہ میداورفارس کے بادشاہوں میں سے ہی کوئی بادشاہ یہاں مراد ہے کیونکہ دانیا ل کی رؤیا نے ان ہی کو ذوالقرنین کانام دیاہے ہم نے دیکھنایہ ہے کہ ان میں سے کونسا بادشاہ یہ صفات اپنے اندر رکھتا ہے.ذوالقرنین سے مراد خورس شاہ ایران ہے سب سے اول اوراہم صفت الہام کی صفت ہے.اس بار ہ میں ہم تاریخ کودیکھتے ہیں توفارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہم کوایساملتاہے کہ جسے الہام ہوتاتھا اورجس کی نیکی اورتقویٰ کی تعریف ہم کو دوسرے انبیاء کے کلام سے بھی ملتی ہے اوریہ بادشا ہ خورس ہے جسے انگریزی میں CYRUS لکھتے ہیں.یسعیاہ نبی اس بار ہ میں لکھتے ہیں :.خورس ملہم تھا ’’خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کاداہناہاتھ پکڑاکہ امتوں کو اس کے قابومیں کروں اوربادشاہوں کی کمریں کھلواڈالوں اوردہرائے ہوئے درواز ے اس کے لئے کھول دوں اوروہ درواز ے بندنہ کئے جائیںگے میں تیرے آگے چلو ں گااورٹیڑھی جگہوں کوسیدھا کروں گامیں پیتل کے دروازو ں کے جداجداپُلوں کوٹکڑے ٹکڑے کروں گااورلوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گااورمیں گڑے ہوئے خزانے اورپوشیدہ مکانوں کے گنج تجھے دوں گاتاکہ توجانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خداہوں جس نے تیرانام لے کے بلایا ہے میں نے اپنے بندے یعقوب اوراپنے برگزیدے اسرائیل کے لئے تجھے تیرانام صاف صاف لے کے بلایا.میں نے تجھے مہربانی سے پکاراگو کہ تومجھ کونہیں جانتا.‘‘(یسعیاہ باب ۴۵ آیت ۱تا۴) یسعیاہ نبی کے اس کلام سے ظاہر ہوتاہے کہ خورس نامی میداورفارس کابادشاہ خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت دیا گیا کیونکہ اسے مسیح کہاگیاہے (یہ حقیقت یاد رکھنے کے قابل ہے کہ خورس کوجوذوالقرنین تھا مسیح کہا گیا ہے اور مسیح موعودکو ذوالقرنین )پھر لکھا ہے کہ اسے حکومت اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے دی تھی.یہی قرآن کریم ذوالقرنین کی نسبت فرماتا ہے اِنَّا مَکَّنَّا لَہٗ فِی الْاَرْضِ وَاٰتَیْنٰہُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ سَبَبًا.ہم نے اسے بادشاہت د ی تھی اورہرضروری امرکوحاصل کرنے کے ذرائع بخشے تھے اسی طرح لکھا ہے کہ میں تیرے آگے چلوں گااورتیر ی ٹیڑھی جگہوں کوسیدھا کرو ںگا.جس سے اشارہ ہے کہ و ہ بہت سفر کرے گا.یعنی قرآن کریم سے ظاہرہوتاہے.پھریسعیاہ کے الہام میں ہے کہ میں خداوند اسرائیل کا خداہوں جس نے تجھے نام لے کے بلایاہے.قرآن کریم میں بھی آتاہے
Page 600
قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ ہم نے ذوالقرنین کو نام لے کرپکاراہے.پھرلکھا ہے میں نے تجھے مہربانی سے پکارا ہے پھر لکھا ہے کہ گوتومجھے نہیں جانتا.اوریہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی پرستش تورات کے نامو ں سے نہیں کرتاتھا بلکہ دوسرے ناموں سے.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ زردشت نبی کاپیروتھا.خورس کی بزرگی کا ثبوت تاریخوں سے خورس کی بزرگی کاثبوت تمام تاریخوں سے ملتاہے.اس کے بارہ میں لکھاہے کہ اس کے دشمن بھی اس سے محبت کرتے تھے.بلکہ جب و ہ کسی حکومت پرحملہ کرتاتواس کی نیکی اوراس کے انصاف کی وجہ سے شہروالے دروازے کھو ل کر اس سے جاکر مل جاتے اوراپنے بادشاہ کو چھو ڑدیتے.یسعیاہ نبی نے بھی اپناالہا م اس بارہ میں لکھا ہے جس کے یہ الفاظ ہیں.’’خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ یہ میراچرواہا ہے وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا.‘‘(باب ۴۴آیت ۲۸)اس کی نیکی اوراس کے اخلا ق کے متعلق مؤرخین نے جوآراء ظاہر کی ہیں وہ یہ ہیں :.ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ دی ہسٹری آف پرشیاجلد ۲ص۵۹۶ (HISTORIANS HISTORY OF THE WORLD )میں مشہور مورخ ڈینو فین کی رائے لکھی ہے کہ:.’’میں نے ایک دفعہ انسانی فطرت پرغورکیااوراس نتیجہ پرپہنچاکہ انسان کے لئے اپنی فطرت کے مطابق دوسرے جانوروں پرحکومت کرناآسان ہے ،مگرانسان پرحکومت کرنامشکل ہے.کیونکہ میں نے غورکیا کہ کتنے ہی آقاہیں جن کے گھر میں تھوڑے یازیاد ہ نوکر ہیںمگروہ اپنے نوکروں سے بھی اطاعت نہیں کرواسکتے.پس اس سے میرایہی خیا ل ہواکہ ایساایک بھی آدمی نہیں جوانسان پرحکومت کرسکتاہو.دوسرے جانداروں پر حکومت کرنے والے کئی ہیں.مگریہ سوچتے سوچتے مجھے خورس بادشاہ کاخیال آیا جس نے میری رائے بدل دی اورمیں نے کہا کہ انسانوں پرحکومت کرنی مشکل نہیں.میں نے دیکھاکہ بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے خوشی سے سائرس کی ماتحتی اختیار کی.حالانکہ بعض ان میں سے ایسے تھے جواس سے دومہینے کی راہ پر بعض چار مہینے کی راہ پر تھے.بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی اسے دیکھاہی نہ تھا اورایسے بھی تھے جنہیں اسے دیکھنے کی توقع بھی نہ ہوسکتی تھی.‘‘ پھر لکھا ہے ’’اس نے لوگوں کے دل میں ایک پرزورخواہش پیداکردی تھی کہ وہ اسے خوش رکھیں اورکہ وہ ہمیشہ ان پرحکومت کرتارہے اس نے اتنی قوموں پرحکومت کی کہ ان کی تعداد کاشمار مشکل ہے مشرق سے مغرب تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی.‘‘ پھر اسی کتاب میں موجودہ زمانہ کے مؤرخین کی رائے کا یہ خلاصہ لکھاہے.’’اگربڑائی انصاف کے لئے لڑنے بلکہ اس کے لئے جان دینے کے لئے تیاررہنے کانام ہے تووہ (یعنی
Page 601
خورس) بڑابادشاہ تھا.‘‘ پھر لکھا ہے :.’’و ہ محض اپنی ذات کے لئے کچھ نہ کرتاتھا.وہ ایساتھاکہ جب میڈیا کی حکومت ،بابل کی حکومت اورمصر والوں نے اتفاق کرکے اس پرحملہ کیا توا س نے محض دفاع کی خاطرتلواراٹھائی.سب سے بڑھ کریہ کہ و ہ رحم مجسم تھا.اس کی ڈھال پرناجائز خون کاقطرہ نہ گراتھا.نہ بھیانک انتقام یا ظلم سے اُس نے ہاتھ رنگے.اس نے مقدونیہ والے بادشاہ کی طرح کبھی شہر نہیں جلائے.اس نے دیگربادشاہوں کی طرح مغلوب بادشاہوں کے ہاتھ پائوں نہیں توڑے ا س نے یہودی بادشاہوں کی طرح کبھی دیواروں پر ان کو نہیں گھسیٹانہ اس نے رومیوں کی طرح مغلوب بادشاہوں کو پھانسی دی.نہ اس نے یونانیو ںکے پاگل خداسکندر کی طرح خونریزی کی.وہ بے شک ایشیائی تھا مگر وہ ایسے لوگوں میں سے تھا جواپنے زمانہ سے بہت پہلے پیداہوجاتے ہیں.و ہ دوسرے انسانوں سے بہت نرم دل تھا.و ہ اپنی قوم کے رواج اوردستورسے بہت آگے نکلا ہواتھا انسانی نسل کی انتہائی ترقی جوآئندہ ہونے والی تھی اس پروہ قائم تھا.اس نے اپنی زبردست حکو مت کی بنیاد اس پر رکھی تھی کہ ملکوں کوفتح کرکے ان کے درجہ کوبڑھایاجائے اورمفتوحوںکو مساوی حقو ق دیئے جائیں.ٹائرکاوہ شہر جس نے نبوکدنضر اورسکندرکے آگے بڑے بڑے محاصروں کے بعد اپنے آپ کوسپردکیا اس شہر نے اس کے جاتے ہی اپنی مرضی سے اپنے دروازے کھو ل دیئے.‘‘پھرلکھا ہے کہ :.’’سب سے بڑھ کر وہ چھوٹی قوم جو یہودی کہلاتی ہے اس نے بابل کے دریا پر اس کا اس طرح استقبال کیا کہ کسی فانی انسان کا استقبال اس نے اس جوش سے کبھی نہیں کیا.‘‘ پھر لکھاہے:.’’وہ اپنے زمانہ کی پیداوارنہ تھا.بلکہ اس نے زمانہ کوپیدا کیا اوروہ اس کا باپ تھا.و ہ تاریخ انسانی میں ایک منفرد اوربے مثل بادشاہ تھا.‘‘(ہسٹورینز ہسٹر ی آف دی ورلڈ جلد ۲ص ۵۹۷تا۶۰۰) اب میں اس مضمون کولیتاہوں کہ وہ خدا تعالیٰ سے سچی خوابیں پانے کامدعی تھا.اسی کتاب میں لکھا ہے کہ و ہ ایک دفعہ ایک مہم پرجارہاتھاکہ اس نے خواب دیکھا.کہ داراؔجواس کارشتہ میں بھتیجاتھا.اس کے دوپر نکلے ہیں ایک یورپ پر پھیلاہواہے اوردوسراایشیا پر.اس نے صبح ا س کے با پ کوبلایا جواس کے ساتھ تھااوراسے کہا تمہارالڑکامعلوم ہوتاہے میرے خلاف سازش کررہاہے.پھراس نے کہا کہ میں اس یقین کی
Page 602
وجہ بھی بتادیتاہوں اوروہ یہ کہ آج میں نے ایسا ایساخواب دیکھا ہے اورخدا تعالیٰ کامیرے ساتھ اس محبت کی وجہ سے جو وہ مجھ سے رکھتاہے یہ سلوک ہے کہ ایسے تمام اہم امورجو میری ذات پرگہرااثر ڈالنے والے ہوں و ہ مجھے بتادیاکرتاہے.(جلد ۲ص ۵۹۵) اس خواب کی تعبیر میں گوا س نے غلطی کھا ئی اورسمجھا ہے کہ شائد دارااس کے خلا ف کوئی ساز ش کررہاہے.لیکن جواس کی تعبیر تھی وہ اپنے وقت پرشاندار طورپر پور ی ہوئی.اورو ہ اس طر ح کہ خورس کے بعد اس کابیٹابادشاہ ہوااوراسے لوگوں نے قتل کردیا.اس پردارانے چندشہزادوں کے ساتھ مل کر اس غاصب کوقتل کردیا اورآخر متفقہ فیصلہ سے داراکوبادشاہ بنایا گیا.جس نے یورپ اورایشیا کے بڑے حصے کوفتح کرکے ایرانی حکومت کو بہت بڑھادیا.(ایضاً) خورس پر الہام ہونے کا ثبوت بائیبل سے بائبل سے بھی معلو م ہوتاہے کہ اسے الہا م ہوتاتھا.کیونکہ بائبل میں لکھا ہے :.’’اورشاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس خاطرکہ خداوند کاکلام جو یرمیاہ کے منہ سے نکلا تھا پوراہو.خداوند نے شاہ فارس خورس کادل اُبھارا کہ اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اوراسے قلمبند بھی کرکے یوں فرمایا.شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخشیں اورمجھے حکم کیا ہے کہ یروشلم کے بیچ جویہوواہ میںہے اس کے لئے ایک مسکن بنائوں.پس اس کی ساری قوم میںسے تمہارے درمیان کون کون ہے اس کا خدااس کے ساتھ ہو اوروہ یروشلم کو جو شہریہوواہ ہے جائے اورخداوند اسرائیل کے خدا کا گھربنائے جو یروشلم میں ہے ‘‘.(عزراباب۱آیت ۱تا۳)گویاخدتعالیٰ نے اسے برگزیدہ کرکے اسے مملکتیں اور حکومتیں بخشیں پھر اسے الہام کرکے یروشلم کامقد س گھربنانے اوریہودیوں کے قید سے رہاکرنے کاحکم دیا.خورس کی ذوالقرنین سے مشابہت از روئے فتوحات دوسری علامت قرآن کریم سے ذوالقرنین کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی فتوحات پہلے مغرب کی طر ف شروع ہوئیں اوروہ ملک پرملک فتح کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ گیا.جہاں اس نے سورج کو ایک ایسے چشمہ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا جس میں سیا ہ مٹی ملی ہوئی تھی(یعنی اس کے پانی کارنگ سیاہ تھا ا س سے مراد بحیرہ اسود ہے جسے انگریز ی میں BLACK SEA کہتے ہیں )چنانچہ خورس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ گذراہے.جب اسے اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی تومغربی ممالک کے باشاہوں نے ایکاکرکے اس پر حملہ کردیا اوراس طرح اس کی فتوحات اپنے ملک سے باہرمغربی طرف شروع ہوئیں اوربابل.نینوااوریونانی نوآبادیات جوایشیائے کوچک کے شمال میں بحیر ہ مارموراتک پھیلی ہوئی تھیں.خورس نے فتح کرلیں اوراس طرح اس
Page 603
چشمہ تک پہنچا.جواس کے ملک کی مغرب کی طر ف تھا اورجس کاپانی سیاہ تھا(یہ تمام علاقے تاریخ سے ثابت ہے کہ ا س نے فتح کئے تھے ).(دیکھو ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ صفحہ ۶۰۷.۶۰۹نیز جیؤش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Cyrus) تیسری علامت قرآ ن کریم نے یہ بیا ن فرمائی ہے کہ مغربی علاقوں کوفتح کرنے کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کی طرف توجہ کی اورتاریخ سے ا س امر کابھی پتہ ملتاہے کہ مغربی علاقوں کی فتح کے بعدخورس نے مشرقی ممالک کوفتح کیا اورافغانستان تک اوربخاراورثمر قند تک اس کی حکومت پھیل گئی (ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈجلد ۲ص ۵۹۳) خورس کی جنگ یاجوج ماجوج سے ہوئی چوتھی علامت قرآ ن کریم بتاتاہے کہ اس نے ان کے درمیا ن بعض علاقوں کی طرف توجہ کی.اوروہاں ایک دیواربنائی.کیونکہ یاجوج ماجو ج وہاں سے حملے کرتے تھے تاریخ سے مندرجہ ذیل امورکاثبوت ملتاہے.اول.خورس کی جنگ یاجو ج ماجو ج سے ہوئی ہے اوراس نے ان کے حملوں سے اپنی مملکت کے بعض علاقوں کو بچایا ہے.یاجوج ماجوج کا مسکن از روئے بائیبل اس مسئلہ کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یاجوج ماجو ج کن قبائل کو کہتے ہیں.اس کے لئے بھی ہم کو بائبل سے مدد ملتی ہے بائبل میں یاجوج ماجوج کی نسبت لکھا ہے.’’اے آدم زاد توجوج کے مقابل جوماجوج کی سرزمین کاہے اورروس اورمسک اورٹوبالسک کاسردارہے اپنا منہ کر اوراس کے برخلاف نبوت کر.‘‘(حزقیل باب ۳۸ آیت ۲) اس سے معلوم ہوتاہے کہ بائبل جس نے سب سے پہلے ہمیں یاجوج و ماجو ج سے روشناس کرایا ہے شمالی علاقہ کے رہنے والے لوگوں کویاجو ج ماجو ج کہتی ہے اوران کا مقام روس،ماسکو اورٹوبالسک بتاتی ہے جو ساراعلاقہ شمالی ہے.اس کے بعد بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ ان کامقابلہ فارس کاکوئی بادشاہ کرے گا کیونکہ لکھا ہے کہ وہ فارس پر قابض ہوگئے ہوے ہیں چنانچہ لکھا ہے.’’اوران کے ساتھ فارس اورکوش اورفوط (ہیں).‘‘(حزقیل باب ۳۸ آیت ۵) یعنی جب یہ پیشگوئی کی گئی ہے.یاجوج کے ماتحت فارس کاعلاقہ تھا.اب ہم تاریخوں کودیکھتے ہیں کہ و ہ یاجوج و ماجوج کی نسبت کیارائے ظاہر کرتی ہیں.پرانے مؤرخو ں میں سے جوزیفس کابیا ن ہے کہ یہ سید ین (SEYTHIENS ) قبائل کانام ہے.تورات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے.کیونکہ پیدائش باب ۱۰ آیت ۲ میں لکھا ہے کہ ’’یافث کے بیٹے یہ ہیں.جمر اورماجوج اورمادی‘‘جمر سِمّیرِ یَنْزْ
Page 604
(CIMMERIANS ) کانام ہے جوایشیائے کوچک کے مشرقی طرف رہتے تھے.اورماد ی میدیا والوں کا نام ہے ان دونوں کے درمیان کاعلاقہ میدینز ہی کاعلاقہ ہے.جیروم لکھتاہے کہ ماجوج کوہ قاف کے اوپر بحیرہ اخضر کے اوپر رہتے ہیں یہ بھی وہی شمالی علاقہ ہے جس میں سیدین رہتے تھے.(جیؤش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Gog and Magog) اس تحقیق کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیساکہ بائبل نے لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج اس زمانہ میں فارس پر حاکم ہوگئے تھے.کیا سیدینز کے بارہ میں یہ امر ثابت ہے سوا س کے متعلق ہم تاریخ میں یہ لکھاپاتے ہیں.’’تب جیسا کہ ہم لکھ آئے ہیں فارس سیدینز کے ہاتھو ں میں آگیا یادوسر ے لفظوں میں مادیوں کے بادشاہ کے ہاتھو ں میں آگیا (مادیاپر اس وقت سیدینز حکومت کررہے تھے )جس باد شاہ کاپائیہ تخت اس وقت اکباتانا (ECBATANA ) میں تھا جس کے ہاتھ سے فارس کو خورس اعظم نے چھڑوایا‘‘.(ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ ہسٹری آف پرشیاجلد ۲ص ۵۸۰) اس واقعہ سے نہ صرف یہ معلو م ہوتا ہے کہ یاجوج ماجو ج کاقبضہ فارس پر ر ہ چکاتھا بلکہ یہ بھی کہ خورس نے یاجوج ماجوج کو شکست دے کر فارس کو ان کے قبضہ سے آزاد کرایا تھا.ان کابار بار حملہ کرکے جنوبی اقوام کو تکلیف دینا بھی تاریخ سے ثابت ہے.چنانچہ ہیروڈیٹس لکھتاہے کہ سیدینز کوہ قاف اوربحیرہ اخضر کے درمیان سے درّہ دربندکے راستے شمالی ممالک کی طرف سے جنوبی ممالک پرحملے کیاکرتے تھے.(ایضاً) دربند کی دیوار ہی یاجوج ماجوج کی دیوار ہے دوسری شق آخری علامت کی قرآن کریم سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچانے کے لئے ایک دیوار بنائی تھی.پہلے توہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس علاقہ میں کسی دیوار کاپتہ ملتاہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں عین اسی مقام پرجسے ہیروڈویس نے سید ینز کے حملہ کاراستہ بتایا ہے دیوار بنی ہوئی تھی.و ہ دربند کی دیوار کے نام سے مشہورہے اورغالباً دربند اسی وجہ سے اس جگہ کانام پڑاہے کہ اس جگہ دیوار کھینچ کر سید ینزکوروکھاگیاتھا.چنانچہ دربند کے متعلق انسائیکلو پیڈیا برٹینکا میں لکھا ہے کہ ا س جگہ ایک دیوار تھی جواپنی تعمیر کے وقت ۲۹فٹ اونچی تھی اوردس فٹ چوڑی تھی اس میں لوہے کے دروازے تھے اورتھوڑے تھوڑے فاصلہ پر نگرانوں کے لئے مینار بنے ہوئے تھے تاکہ وہاں سے نگرانی کرسکیں یہ پچاس میل لمبی ہے اور بحیرہ اخضر سے کوہ قاف تک چلی گئی ہے پھر انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں لکھا ہے کہ یہ دیوار سکندر کی دیوارہے.مگراسے قباد ؔ نے جوساسانی بادشاہ تھا دوبار ہ مرمت کروایا تھا.(زیر لفظ Derbent) سکندر کا اس دیوار کو بنانا خلاف عقل ہے ان بیانات سے یہ تومعلوم ہوگیا کہ یہاں کوئی دیوار موجو د تھی.
Page 605
مگریہ کہ اس دیوار کو خورس نے بنایاتھا.اس کا ثبوت تاریخ سے اس وقت تک مجھے نہیں مل سکا.ہاں میں سمجھتاہوں کہ سکندرکااس دیوارکو بنانا بالکل خلاف عقل ہے.سکندر کے متعلق تاریخ سے معلوم ہوتاہے کہ ۳۳۰ قبل مسیح کی گرمی کے موسم میں اس نے داراکو آخر ی شکست دی ہے اورداراماراگیاہے.(انسائیکلوپیڈیا برٹینکا زیر لفظ Elxender the Great)لیکن اس فتح سے اسے ایران پرقبضہ حاصل نہیں ہو ا.بلکہ اس کے مقابل پر کئی صوبوں کے لشکر ابھی موجود تھے اس لئے وہ بغیر دم لئے آگے بڑھتاگیا.لیکن جونہی وہ آگے بڑھا پچھلے علاقہ میں بغاوت ہوگئی اوراسے واپس آنا پڑا.بغاوت کو فرو کرکے سکندر کابل کی طرف بڑھا جہاں اس کی فوج میں بغاوت شروع ہوگئی.اورمورخین کے نزدیک ۳۲۹ قبل مسیح کی سردی کے موسم میں وہ ہندوستان کی طرف بڑھا.یہ سفراس قد رسرعت سے طے ہواہےکہ بعض مورخ اس کے متعلق شک ظاہر کرتے ہیں.بہرحال یہ امر ثابت ہے کہ سکندر راستہ میں کہیں ٹھہرانہیں.بلکہ لڑتابھڑتاہندوستان کی طرف چلاگیا ہے.جہاں سے وہ جہازوں کے راستہ واپس لوٹا.اور ۳۲۴ قبل مسیح میں ایران پہنچا وہاں تھوڑاساعرصہ رہنے کے بعد جس میں اسے اپنی فوجوں کی بغاوت فروکرنے کی پھر ضرورت پیش آئی وہ گھرکوروانہ ہو ا.اور۱۳؍جون ۳۲۳ قبل مسیح راستہ ہی میں مرگیا (ایضاً).ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اتنی بڑی دیوار بنانے کاہرگز موقع نہ مل سکتاتھا.پس معلوم ہوتاہے کہ یہ دھوکا اس امر سے لگاہے کہ بعض مسلمان مفسرین کاخیا ل تھا کہ سکند رذوالقرنین تھا (کشاف والقرطبی زیر آیت ھذا).پس اس سے مسیحی مصنفوںنے دھوکا کھا کر اس دیوار کو سکند رکی دیوار سمجھ لیا.مگر صرف اتنا ثابت کرناکافی نہیں کہ سکندرنے یہ دیوار نہیں بنائی بلکہ اس سے زیادہ ایسے ثبوت کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہوکہ یہ دیوار اگر یقیناً نہیں توغالباً خورس نے بنائی تھی چونکہ تاریخ سے اس وقت تک کوئی ایساثبوت نہیں ملا جس سے قطعی طور پر ثابت ہوکہ یہ دیوا رخورس نے بنائی ہے.ہم قیاس سے ہی کام لے سکتے ہیں.چنانچہ میں نے تاریخی واقعات کی بناء پر یہ نتیجہ نکالاہے کہ یہ دیوار خورس ہی نے بنائی ہے اور میرے دلائل یہ ہیں.دلائل کہ یہ دیوار خورس نے بنائی (۱)تاریخ سے معلوم ہوتاہے کہ دارانے جو خورس کے بیٹے کے بعد بادشاہ ہوااورجس کے متعلق خورس نے خواب دیکھی تھی کہ مشرق و مغر ب میں اس کی حکومت ہوگی.سیدینز کازورتوڑنے کے لئے یونان میں سے گزر کریوروپ کی طرف سے جاکر سیدینز پرحملہ کیاتھا(ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ صفحہ ۶۱۰).اب یہ بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے کہ جبکہ سیدینز اس کے شمالی جانب اس کے ملک کے پاس ہی بستے تھے وہ ان پرحملہ کرنے کے لئے یورپ سے گیا ہو.پس اس واقعہ سے قیاس کیاجاسکتاہے کہ چونکہ خورس نے دربند کے پاس
Page 606
دیوار بنادی تھی اورایک بڑی فوج کو لے کر ان کے ملک پر صرف چند چھوٹے چھوٹے دروازوں سے حملہ کرنا خالی از خطرہ نہ تھا.اوردیوار کوتوڑنا اوربھی پُرخطرتھا.پس دارانے سیدینز کازورتوڑنے کے لئے یوروپ کی طرف سے جاکر حملہ کیا.تاکہ ایک طرف سے دیوار ان کوروک رہی ہو اوردوسری طرف سے اس کی فوجیں ان پر حملہ آورہوجائیں.(۲)دوسراامر جس سے اس بار ہ میں قیاس کیاجاسکتا ہے یہ ہے کہ اگر درّہ دربند میں داراسے پہلے دیوار موجودنہ تھی تودارائے اول جیسے عقل مند بادشاہ کی نسبت یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے ملک کوننگاچھوڑ کر ہزارمیل کاچکر کاٹ کر سیدینز پر حملہ کرنے کے لئے گیا تھا.کیونکہ اس صورت میں یہ صریح خطرہ موجود تھا کہ اس کے جانے کے بعد سیدینز بغل میں سے نکل کر اس کے ملک پرحملہ کردیتے اورنہ و ہ اپنے ملک کوہی بچاسکتا.نہ اس کاملک اس کی ضرورت پرمزید کمک بھجواسکتا.پس اس کااطمینان سے یورپ کی طرف سے جاکر حملہ کرنا بتاتاہے کہ دربند کی طرف سے اس سے پہلے دیوار موجود تھی اوروہ اس امر سے مطمئن تھا کہ سیدینز اس کے ملک پر دیوار کی وجہ سے اس طرف سے حملہ نہیں کرسکتے.دربند کے پاس دیوار بنانے والا خورس ہی تھا میں سمجھتاہوں کہ اب میں چاروں علامتوں کو سوائے دیوار والے حصہ کے یقینی طورپر خورس کے حق میں ثابت کرچکاہوں.اوردیوار والے حصہ کے متعلق بھی اس قدر ثابت کرنے میں کامیاب ہوگیا ہوں کہ جہاں تک اس زمانہ کے واقعات سے(جودرحقیقت بہت کم ہم تک پہنچے ہیں ) قیاس کیاجاسکتاہے کہ خورس ہی دربند کے پاس دیوار بنانے والاتھا.خصوصاً جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج خورس کے برسراقتدار آنے سے پہلے اس کے اپنے ملک پرقابض تھے اوران کے حملے فارس پر اوراس کی وسیع سلطنت پر برابر جاری تھے.اورجبکہ ہم کو تاریخ سے یہ مزید ثبوت ملتاہے کہ دربند کی طرف سے سیدینز کے حملے خورس کے زمانہ کے بعد رک گئے تھے.(ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ صفحہ ۵۸۹) خلاصہ یہ کہ یہ امر ایک ثابت شدہ حقیقت معلوم ہوتاہے کہ ذوالقرنین بادشاہ سے مراد قرآن کریم میں خورس بادشاہ ہی ہے اوراس امر کے ثابت کرچکنے کے بعد میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیر الگ الگ بیان کرتاہوں.
Page 607
اِنَّا مَكَّنَّا لَهٗ فِي الْاَرْضِ وَ اٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًاۙ۰۰۸۵ ہم نے یقیناً اسے زمین میں حکومت بخشی تھی.اورہم نے اسے ہرایک چیز (کے حصول )کاذریعہ عطا کیاتھا.حلّ لُغَات.مَکَّنَّا مَکَّنَّامَکَّنَ سے جمع متکلم کاصیغہ ہے.اور مَکَّنَہٗ مِنَ الشَّیْءِ کے معنے ہیں جَعَلَ لَہُ عَلَیْہِ سُلْطَانًا وَّقُدْرَۃً.اس کوکسی بات پرطاقت قدرت اورغلبہ بخشا(اقرب)پس مَکَّنَّا کے معنے ہوں گے.ہم نے اسے حکومت و غلبہ دیاتھا.سَبَبًا سَبَبًا مَایُتَوَصَّلُ بہٖ اِلَی غَیْرِہٖ.کسی چیز کے حصو ل کے ذریعہ کو سبب کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.یعنی ہم نے ذوالقرنین کو دنیا میں بڑی طاقت بخشی تھی.اورہرقسم کے سامان اسے بخشے تھے یہ اوپر ثابت کیاجاچکا ہے کہ خورس کواللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خاص طات دی تھی.جیساکہ بائبل اوراس کے اپنے بیانات سے ثابت کیاجاچکاہے.دیکھونوٹ نمبر۱ فَاَتْبَعَ سَبَبًا۰۰۸۶حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تب وہ ایک راستہ پر چل پڑا.یہاں تک کہ وہ سورج ڈوبنے کے مقام پر پہنچا تواس نے ایساپایا کہ (گویا)وہ ایک گدلے تَغْرُبُ فِيْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَّ وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا١ؕ۬ قُلْنَا يٰذَا چشمے میں ڈوب رہاہےاوراس نے اس کے پاس کچھ لوگ (آباد )پائے (اس پر )ہم نے (اسے)کہا (کہ ) الْقَرْنَيْنِ اِمَّاۤ اَنْ تُعَذِّبَ وَ اِمَّاۤ اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا۰۰۸۷ اے ذوالقرنین تجھے اجازتہے کہ ان کو عذاب دے یاان کے بارہ میں حسن سلوک سے کام لے حلّ لُغَات.حَمِئَۃٌ اَلْحَمِئَۃُ کے معنے ہیں ذَاتُ الْحَمْأَۃِ.کیچڑ والا(اقرب)پس عَيْنٍ حَمِئَةٍ کے معنے گدلا.کیچڑ والاچشمہ.تفسیر.مَغْرِبَ الشَّمْسِ سے یہ مراد نہیں کہ دنیا کے آخر ی سرے پرپہنچا.بلکہ مراد یہ ہے کہ اپنی فتوحات کی مغربی حدتک جا پہنچااورمراد ایشاء کوچک کی شمالی اورمغر بی حد ہے.
Page 608
عَيْنٍ حَمِئَةٍ سے مراد بحیرہ کیسپین عَيْنٍ حَمِئَةٍ کے معنے مٹی ملے ہوئے پانی کے ہیں.اورمراد بحیرہ اسود سے ہے.کیونکہ مٹی سے پانی کارنگ گدلا اورسیاہی مائل ہو جاتا ہے اوراس سمندر کاپانی بوجہ عمیق گہرائی کے سیاہی مائل ہے.مٹی ملے ہوئے کے الفاظ لفظاًبھی اس سمندر پرصادق آتے ہیں.کیونکہ یہ سمند رسارے سمندروں سے اس امرمیںنرالاہے کہ اس میں باقی سمندروں کی نسبت نمکین پانی کم شامل ہوتاہے اوراس کے پانیوں کابڑاحصہ زمینی دریائوں کے پانی سے بنتاہے.جوروس آرمینیا اوربلغاریہ کے ملکوں سے آکر اس میں گرتے ہیں (انسائیکلوپیڈیا برٹینکا زیر لفظ بلیک سی)پس چونکہ اکثر پانی اس کادریائو ںسے آتاہے اس میں دوسرے سمندروں کی نسبت مٹی کی آمیزش زیادہ ہے اورنمک سب سمندروں سے کم ہے.یہ جوفرمایا کہ اس میں سورج ڈوبتاہواپایا.اس سے مرادیہ ہے کہ چشمہ کے لفظ سے دھوکانہ کھائو.چشمہ سے صرف یہ مراد ہے کہ اس کاپانی گہراہے اورسطح زمین کے اندرسے نکل کر بھی اس میں پانی ملتارہتاہے ورنہ چھوٹاچشمہ مراد نہیں.بلکہ وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کے کنارہ پرکھڑے ہوں تو یوں معلوم ہوگا کہ گویا سورج اسی میں ڈوب رہاہے.وَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًاسے مراد وہ حکومت ہے جوایشائے کوچک کے مشرقی ساحل پر حکومت کررہی تھی اورجس نے بابل کی فتح کے بعد دوسری حکومتوں سے مل کر بلاوجہ خورس پر حملہ کردیاتھا.اس قوم کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے اسے کہا کہ خواہ اس کی شرارت کی اسے سزادوخواہ ان پر احسان کرکے اپناگروید ہ بنالو.قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ اس نے کہا(ہاں میں ایسا ہی کروں گا اور)جوظلم کرے گا اسے توہم ضرورسزادیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُّكْرًا۰۰۸۸ لوٹایاجائے گااوروہ اسے سخت عذاب دے گا تفسیر.یعنی خورس نے اس الہام کے جواب میںیہ عرض کی کہ میرایہ منشاء ہے کہ اگر یہ دوبارہ شرارت کریں توان کوسزادوں ورنہ نہیں.یہ جوفرمایا ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ اس سے معلوم ہوتاہے کہ خورس کا ایک ایسے مذہب سے تعلق تھا جوقیامت پر خاص
Page 609
طور پر ایمان رکھتاتھا.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ خورس زردشتی مذہب کامخلص پیروتھا.جومذہب کہ اسلام کے بعدسب مذاہب سے زیادہ بعث بعد الموت پرزوردیتاہے (جیؤش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Cyrus)اس میں لکھاہے کہ یہ امر یقینی طورپرثابت ہے کہ خورس خالص زردشتی مذہب کاپیروتھا.وَ اَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَآءَ ا۟لْحُسْنٰى١ۚ وَ اورجوایمان لائے گااورنیک(اورمناسب حال) عمل کرے گاتواس کے لئے (خدا تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال سَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًاؕ۰۰۸۹ کے)بدلہ میں اچھا انجام (مقدر)ہے اورہم(بھی )ضروراس کے لئے اپنے معاملہ میں آسانی والی بات کہیں گے.تفسیر.ذوالقرنین کے اخلاق اس آیت سے ذوالقرنین کے اخلاق کاپتہ چلتاہے اورجیسا کہ نوٹ نمبر(۱)میں بتایاجاچکا ہے.خورس بہت رحم دل تھااورمفتوح اقوام سے نہایت محبت اوررحم کاسلوک کرتاتھا.اس جگہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ چاہوتوسزادوچاہوتورحم کر و.تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک لطیف طریق رحم کی تعلیم دینے کاہے پہلے عذاب کا ذکر کیا کہ اس قوم نے شرارت توکی ہے اور تمہاراحق ہے کہ ان کوسزادو.پھر یہ فرما دیاکہ اگرچاہوتوان پر رحم بھی کرسکتے ہو.یعنی ایک راستہ رحم کابھی کھلا ہے.اس طرح رحم کی طرف ایک لطیف اشارہ کرکے ذوالقرنین کو خالص نیکی کاموقعہ عطا کیا.اگر حکماً رحم کرنے کو کہا جاتا تو ذوالقرنین کے طبعی نیکی کے اظہار کاموقعہ نہ ملتا.لیکن اس حکم کے بعدجواس نے نیکی کی یہ اس کاذاتی فعل تھااوراسے زیادہ ثواب کامستحق بناتاتھا.ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا۰۰۹۰حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا پھر وہ ایک اورراستہ پر چل پڑا.یہاں تک کہ جب وہ سورج کے نکلنے کے مقام پرپہنچا تواس نے اسے ایسے لوگوں پر تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًاۙ۰۰۹۱ چڑھتاپایا.جن کے لئے ہم نے (ان کے اور)اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں بنایاتھا.تفسیر.ذوالقرنین کے مشرقی سفر کے حالات اس میں ذوالقرنین کے مشرقی سفر کا ذکر فرمایا
Page 610
ہے جوافغانستان تک ہوا.لَمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ قوم ایسی مہذب نہ تھی اورمکان وغیرہ ان میں کم تھے.بلکہ جھونپڑوں یا خیمو ں میں رہتے تھے.افغانی قبائل کی اس وقت یہی حالت تھی.وہ تہذیب کے اعلیٰ مقام پر نہ تھے.مگرمیرے نزدیک الفاظ قرآن پر غورکرنے سے یہ معلوم ہوتاہے کہ وہ بلوچستان کاعلاقہ تھا.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا.کہ اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ ایسی قوم پرچڑھتاہے جس کے اورسورج کے درمیا ن ہم نے کوئی پردہ نہیں بنایا یعنی اوٹ کوئی نہیں.سیدھی شعاعیں اس پر پڑتی ہیں.مطلب یہ کہ وہ علاقہ چٹیل میدان ہے.درخت وغیرہ یااونچے پہاڑ ا س علاقہ میں نہیں.عام طورپر مورخین یونانی ہی ہیں اس لئے انہوں نے اپنی طرف کے علاقوں کی فتوحات کاہی ذکر کیا ہے.مشرقی طرف کی فتوحات کا ذکر بالتفصیل نہیں کیا.ہاں اختصاراً وہ یہ لکھتے ہیں کہ خورس نے مشرق کی طرف افغانستان کے نواح میں حملہ کیا تھااوراس علاقہ کوفتح کرلیاتھا.مگرچونکہ سیستان بھی فارسی حکومت میں شامل تھا.میرے نزدیک یہ بلوچستان کے علاقہ کا ذکرمعلوم ہوتاہے جہاں ریت کاصحرااورٹیلے وغیر ہ ہیں.لیکن اگر تاریخ کے بیان کوکافی سمجھاجائے توپھر لَمْ نَجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا سے اس صحرااورمیدان میں بسنے والی قوم مراد لی جائے گی جو سیستان اورہرات کے مغربی جانب اوردُزداب سے شمالی جانب کومشہد تک کئی سومیل تک لمباچلاگیاہے.كَذٰلِكَ١ؕ وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا۰۰۹۲ (یہ واقعہ ٹھیک )اسی طرح تھااورجوکچھ اس کے پاس تھا اس کاہم نے (اپنے )علم سے احاطہ کیا(ہوا)تھا.تفسیر.یعنی جس طرح ہم نے بتایاہے ایسا ہی ہواتھایعنی اس کا ان علاقوں کو فتح کرنا ایک یقینی بات ہے وَ قَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًاسے مرادیہ ہے کہ ہم اس کی ہرسفر میں حفاظت کرتے تھے کیونکہ اس کی ہربات کی خبررکھنے کے یہی معنے ہیں کہ اس کے حالات کی نگرانی کرتے تھے.ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا۰۰۹۳ پھر و ہ ایک راستہ پر چل پڑا.تفسیر.اس تیسرے اَتْبَعَ سَبَبًامیں خورس بادشاہ کے اس سفرکا ذکر ہے جواس نے ایران سے شمالی
Page 611
جانب بحیرہ کیسپین اورکوہ قاف کے درمیا نی علاقہ کی جانب کیا.(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Cyrus) حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا١ۙ لَّا یہاں تک کہ جب وہ دوپہاڑوں کے درمیان پہنچا تواس نے ان کے ورے کچھ ایسے لوگ پائے جوبمشکل اس يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا۰۰۹۴ کی بات سمجھتے تھے.حل لغات.السَّدَّیْنِ السَّدَّیْنِ اَلسَّدُّ سے تثنیہ ہے اوراَلسَّدُّ کے معنے ہیں.الْجَبَلُ پہاڑ.اَلْحَاجِزُ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ.دوچیزوں کے درمیان روک.(اقرب) تفسیر.اس جگہ کے بسنے والوں کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ بمشکل ذوالقرنین کے لوگوں کی باتیں سمجھتے تھے یہ پہلے بتایاجاچکاہے کہ کَادَ سے پہلے نفی آئے تواس کے معنے مثبت کے ہوتے ہیںاورمثبت کالفظ آئے تواس کے معنے نفی کے ہوتے ہیں.پس اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ بمشکل ذوالقرنین اوراس کی قوم کی بات سمجھتے تھے.مگرساتھ ہی یہ بھی نکلتاہے کہ و ہ بات کسی حد تک سمجھ جاتے تھے.اس سے ظاہر ہے کہ وہ فارس کے لوگوں کے ہمسائے اوران کے ساتھ میل ملاپ رکھنے والے تھے.پس گوان کی زبان اورتھی مگر ہمسائگت اورکثر ت سے میل جول رکھنے کی وجہ سے فارس اورمیدیاوالوں کی کچھ کچھ بات وہ سمجھ لیتے تھے.جغرافیہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتاہے کہ دربندکاعلاقہ جس کی نسبت بتایا جاچکا ہے کہ وہاں دیوار بنائی گئی تھی ایسا ہی علاقہ ہے یہ علاقہ مادہ اورفارس کے ساتھ لگتاہے بلکہ بعد کے زمانہ میں توفارس کاحصہ ہی بن گیا تھا.گواب روس والوں نے اس علاقہ کو لے کر اپنی حکومت میں شامل کرلیا ہے.یہ جو فرمایا ہے کہ بَيْنَ السَّدَّيْنِ پہنچا اس سے مراد یہ ہے کہ اس راستہ کے ایک طرف بحیرہ اخضر ہے اوردوسری طرف کوہ قاف.اوریہ دونوں چیزیںدونوں طرف سے سدّیعنی روک کاکام دے رہی تھیں.صرف درمیانی درّ ہ غیرمحفوظ تھا.
Page 612
قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي انہوں نے کہا (کہ )اے ذوالقرنین یاجوج ماجو ج یقیناً اس ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ پس کیاہم (لوگ )آپ کے لئے کچھ خراج اس شرط پرمقررکردیں کہ آپ ہمارے درمیان اوران کے درمیان بَيْنَهُمْ سَدًّا۰۰۹۵ ایک روک بنادیں.حلّ لُغَا ت.خَرْجًا اَلْخَرْجُ.اَلْخَرَاجُ خَرْجٌ کے معنے خراج یعنی لگان کے ہیں.(اقرب) تفسیر.یعنی چونکہ یہ لوگ یاجوج وماجو ج کے دروازہ پر تھے وہ کثرت سے ان کے حملوں کاشکار ہوتے رہتے تھے.اس لئے اس علاقہ کے لوگوں نے خورس سے خواہش کی کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لئے ایک دیواربنا دی جائے اوراس کاخرچ ہم دیں گے.قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ۠ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ اس نے کہا (کہ )اس (قسم کے کاموں )کے متعلق میرے رب نے جوطاقت مجھے بخشی ہے وہ (دشمنوں کے بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًاۙ۰۰۹۶ سامانوں سے )بہت بہترہے اس لئے تم مجھے (اپنے )مقدوربھر مدد دوتاکہ میں تمہار ے درمیان اوران کے درمیان ایک روک بنادوں حل لغات.رَدْمًا اَلرَّدْمُ مَایَسْقُطُ مِنَ الْجِدَارِ الْمُھْدَمِ.گری ہوئی دیوار کاڈھیر( اقرب) تفسیر.یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کاخو ب علم دیاہے اورمیں اس کام کوخوب اچھی طرح کرسکتا ہوں اس لئے تم مزدوری کے ذریعہ سے میری مددکروتاکہ میں یہ دیواربنادوں.قُوَّۃٌ سے مراد مزدوری ہے یعنی تم لوگ اس جگہ بستے ہو.مزدوری کاکام تم ہی کرسکتے ہو.پس میںسکیم تجویز
Page 613
کرتاہوں تم اس کے پوراکرنے میں میراہاتھ بٹائو.اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ١ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ تم مجھے لوہے کے ٹکڑے دو(چنانچہ وہ روک تیارہونے لگی )یہاں تک کہ جب اس نے (پہاڑی کی )ان (دونوں ) قَالَ انْفُخُوْا١ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا١ۙ قَالَ اٰتُوْنِيْۤ اُفْرِغْ چوٹیوں کے درمیان برابری پیداکردی تواس نے (ان سے )کہا (کہ ا ب اس پرآگ)دھونکو.حتی کہ جب اس عَلَيْهِ قِطْرًاؕ۰۰۹۷ نے اسے (بالکل)آگ (کی طرح )کردیاتو(ان سے )کہا(کہ اب)مجھے(گلاہوا)تانبا(لا)دوتاکہ میں (اسے ) اس پر ڈال دوں.حلّ لُغَات.زبرالحدید:زُبُرٌ.زبرۃٌ کی جمع ہے اوراَلزَّبْرَۃُ کے معنے ہیں اَلْقِطْعَۃُ الضَّخْمَۃُ بڑاٹکڑا(اقرب)پس زُبَرَ الْحَدِيْدِکے معنے ہوں گے لوہے کے ٹکڑے.ساوٰی سَاوَی الشَّیْئَیْنِ وَسَاوٰی بَیْنَھُمَا کے معنے ہیں سَوَّی دونوں کے درمیان برابری کردی.(اقرب) الصَّدَفَیْنِ:اَلصَّدَفَیْنِ اَلصَّدَفُ سے تثنیہ ہے اوراَلصَّدَفُ کے معنے ہیں کُلُّ شَیْءٍ مُرْتَفِعٍ عَظِیْمٍ.ہراونچی بلند چیز.اَلْجَبَلُ.پہاڑسَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ اَیْ بَیْنَ رَأْسَیَ الْجَبَلِ الْمُتَقَابَلَیْنِ.آمنے سامنے کے دونوں پہاڑوںکی چوٹیوں کے درمیان برابری پیداکردی (اقرب) اُفْرِغْ اَفْرَغَ الْمَاءَ کے معنے ہیں :صَبَّہٗ اس نے پانی کوڈالا.اَفْرَغَ الدِّمَاءَ: اَرَاقَھَا.خون بہایا.اَفْرَغَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّۃَ : صَبَّھَا فِی قَالِبٍ سونے اورچاند ی کو کسی سانچے میں ڈال کرڈھالا.(اقرب) اَلْقِطْرُ اَلنُّحَاسُ الذَّائِبُ پگھلاہواتانبا(اقرب)اٰتُوْنِيْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا کے معنے ہوں گے تم مجھے تانبالادو کہ میں اس پر ڈالو ں.تفسیر.یعنی علاوہ مزدوری کے تم یہ مددبھی دو کہ لوہااور تانبامہیاکرو.کیونکہ گودیوار بناناحفاظت کے لئے ضروری تھا مگراس کے ساتھ دیوار میں دروازے بنانے بھی ضروری تھے.تاکہ تجارت کو نقصان نہ پہنچے اورتجارتی
Page 614
قافلوں کے آنے جانے کاراستہ کھلارہے.پس مضبوط در واز ے بنانے کے لئے لوہے کی اوران کو زنگ سے بچانے کے لئے تانبے کی ضرورت تھی جوان سے طلب کیا گیا.فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا۰۰۹۸ پس (جب وہ دیوار تیار ہوگئی تو)و ہ(یعنی یاجوج ماجو ج)اس پر چڑھ نہ سکے اورنہ اس میں کوئی سوراخ کرسکے.تفسیر.یعنی جب دیوار بن گئی.تویاجوج وماجو ج کے حملے رک گئے.وہ دیوار اس قدراونچی تھی کہ وہ اس پرچڑھ بھی نہیں سکتے تھے اوراتنی موٹی تھی کہ اس میں نقب بھی نہیں لگاسکتے تھے.یہ مراد نہیں کہ دیواراس قسم کی تھی کہ اس پرچڑھنا یااس میں نقب لگانا ناممکن تھا.بلکہ چونکہ اس میں بُرج اورقلعے تعمیر کئے گئے تھے جہاں سپاہی پہرہ کے لئے مقرررہتے تھے اس لئے دیوار پر چڑھنایانقب لگاناناممکن تھا.کیونکہ پہرہ دارہراس شخص کو جو چڑھنے کی کوشش کرے یانقب لگائے مارسکتے تھے.ظاہر ہے کہ جو دیوارپر چڑھنے میں یانقب لگانے میں مشغول ہو وہ لڑ نہیں سکتا.اودیوارکے اوپر بیٹھے ہوئے سپاہی اس کاآسانی سے مقابلہ کرسکتے ہیں اوراسے روک سکتے ہیں.قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ١ۚ فَاِذَا جَآءَ (اس پر )اس نے کہا (کہ)یہ(کام محض)میرے رب کے خاص احسان سے(ہوا)ہے.پھر جب (عالمگیر وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ١ۚ وَ كَانَ وَعْدُ عذاب کے متعلق ) میرے رب کاوعدہ (پوراہونے پر)آئے گاتووہ اسے(توڑکر)ایک زمین سے پیوست شدہ رَبِّيْ حَقًّاؕ۰۰۹۹ ٹیلابنادے گااور میرے رب کاوعدہ (ضرور)پوراہوکر رہنے والا ہے.تفسیر.مومنوں کو تکبر سے بچنے کی نصیحت یہ فقر ہ اس کے ایمان کے اظہارکے لئے بیان
Page 615
کیاگیاہے اوربتایا ہے کہ مومن بڑے سے بڑاکام کرکے بھی متکبر نہیں ہوتا.بلکہ اپنے کاموں کواللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتاہے.فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ.اس سے معلوم ہوتاہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہا م خورس کوبتادیاتھا کہ ایک دن یہ قومیں پھر جنوب مشرق کی طرف بڑھیں گی اوریہ دیوار بیکار ہوجائے گی.کیونکہ دیوارٹوٹنے سے یہی مراد ہے جس کاثبوت انبیاء ع۷ کی آیات سے ملتاہے.کیونکہ وہاںصاف لکھاہے کہ یہ قومیں سمندرکے ذریعہ سے دنیا میں پھیلیں گی.یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیوارٹوٹنے سے مراد مسلمانوں کی حکومت کازوال ہو.وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِي اور(جب اس کے پوراہونے کا وقت آئے گاتو)اس وقت ہم انہیں ایک دوسرے کے خلاف جوش سے حملہ الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًاۙ۰۰۱۰۰ آورہوتے ہوئے چھو ڑ دیں گے اوربگل بجایا جائے گاتب ہم ان (سب)کوبالکل اکٹھاکردیں گے.تفسیر.یہاں سے اللہ تعالیٰ کاکلام شروع ہوتاہے.اوربتایاہے کہ جب اس وعد ہ کا وقت آئے گا جس کا ذکر ذوالقرنین نے کیا تھا.اللہ تعالیٰ ان اقوام کو پھر ترقی دےگااورمختلف اقوام عالم آپس میں لڑیں گی اورشمالی اورمغربی اقوام ،جنوبی اورمشرقی اقوام سے مل جائیں گی اوراللہ تعالیٰ سب دنیاکو جمع کردے گا یعنی وہ ایسا زمانہ ہوگاکہ سفرآسان ہوں گے اورساری دنیاایک ملک کی طرح ہوجائے گی چنانچہ موجودہ زمانہ ایسا ہی ہے.قرآن کریم میں دوسری جگہ یاجو ج وماجوج کے پھیلنے کا ذکران الفاظ میں کیاگیاہے حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَ مَاْجُوْجُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ.وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا١ؕ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ.(الانبیاء :۹۷،۹۸) یعنی جب یاجو ج ماجوج کی روک کو ہم دورکردیں گے اوروہ سمندرکی لہروں پرسے تیزی سے سفر کرتے ہوئے سب دنیا میں پھیل جائیں گے اس کے بعد ہماراوعدہ ان کی تباہی کے متعلق پوراہو گااورعذاب آئے گاتب و ہ حیران ہوکر کہیں گے کہ ہمیںتواس عذاب کاخیال تک نہ تھا اورہم تودنیا پر ظلم کرتے رہے.اب ہماری تباہی میں کیاشک ہے.اس آیت میں یہ بھی بتایاگیاہے کہ یاجوج ماجوج مشرق کی طرف کسی دیوار کے رخنہ میں سے نہیں بلکہ سمندر کے راستہ سے آئیں گے اوریہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان
Page 616
کاسمندروں پرقبضہ ہوگا.اورسب دنیا کے سمندروں پر ان کے جہاز چلیں گے.کیونکہ مِنْ کُلِّ حَدَبٍ کے الفاظ آیت میں استعمال ہوئے ہیں جن کے معنے ہیں کہ سمندرکی سب لہروں پرسے وہ آئیں گے.نیزاس آیت میں یہ بھی بتایاگیاہے کہ ان کے یہ سفربڑی جلدی سے طے ہوں گے.اس سے دخانی جہازوں کی ایجاد کی طرف اشارہ ہے چنانچہ دیکھ لویہ پیشگوئی کس طرح حرف بہ حرف پو ری ہوئی.سمندرہی کے ذریعہ سے یہ اقوام مشرق میں پھیلیں.اورسمندر ی سفر جس طر ح ان کے زمانہ میں جلدی طے ہونے لگاہے اس کی نظیر پہلے نہیں ملتی.وَّ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَىِٕذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَاۙ۰۰۱۰۱ اورہم اس دن جہنم کو کافروں کے بالکل سامنے لے آئیں گے تفسیر.و ہ دن جہنم کے سے ہوں گے ایک دوسرے سے دشمنی بڑھ جائے گی اورملک ملک پرغلبہ پانے کی کوشش کرے گااوریہ بھی مراد ہے کہ یہ اقوام سخت بے دین ہو ںگی اوراللہ تعالیٰ سے غافل.اورایسے کام کریں گی جوانسان کوجہنم کامستحق بنادیتے ہیں.ا۟لَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَ كَانُوْا لَا جن کی آنکھیں میرے ذکر(یعنی قرآن کریم )کی طرف سے (غفلت کے )پردہ میں تھیں اوروہ سننے کی طاقت يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ سَمْعًاؒ۰۰۱۰۲ (بھی )نہیں رکھتے تھے تفسیر.اس میں بتایاہے کہ عبادت اس قوم سے بالکل اٹھ جائےگی اوریا توشروع زمانہء ترقی میں خدا تعالیٰ کے لئے انہوں نے بڑی بڑی تکالیف اٹھائی تھیں اوریااس زمانہ میں یہ حال ہوگاکہ اللہ تعالیٰ کانام مٹ جائے گااوریہ لوگ ہرکام کو اپنے کما ل کی طرف منسوب کریں گے.وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ سَمْعًا میں بتایاہے کہ اس قدرزنگ دل پر لگ جائے گاکہ خدا کاکلام سننے کی طاقت اور رغبت بالکل دلوں سے جاتی رہے گی.چنانچہ ا س وقت مغربی اقوام کایہی حا ل ہے خداکے نئے کلام کاسننا توالگ
Page 617
بات ہے.وہ اس کلام کی بھی دھجیاں اڑارہے ہیں جس کوظاہر میںتسلیم کرتے ہیں اورآئے دن ان میں کتب لکھی جاتی ہیں.جن میں کبھی توحضرت مسیح ؑ کو ایک خیالی وجود ثابت کیا جاتا ہے.کبھی بائیبل پر جرح کرکے اسے انسانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.رکوع پراجمالی نظر اوپرکی آیات میں مسیحی اقوام کی آخری زمانہ کی ترقی اوردنیا میں پھیل جانے اوردین سے بے پرواہ ہوجانے اورخدا تعالیٰ کو بھول جانے کا ذکرکیاگیاہے اوربتایا ہے کہ اس ترقی کے بعد اللہ تعالیٰ غیب سے سامان پیداکرے گااوران کی ترقی تنزل سے بدل جائے گی.تب مایو س ہوکر موسیٰ ؑ کے کشف کے مطابق ان کو دین کی طرف توجہ ہوگی اوروہ اپنی غلطی کومحسوس کرکے پھر مجمع البحرین کی طر ف لوٹیں گے اوراسلام کی طرف رجوع کریں گے.میں اس جگہ یاجوج و ماجوج کے انجا م کے متعلق جوپیشگوئیاں بائبل میں ہیں ان کو بھی لکھ دینا مناسب سمجھتاہوں.مکاشفا ت باب ۲۰ آیات ۷،۸ میں لکھا ہے کہ ’’جب ہزاربرس پورے ہوچکیں گے توشیطان قید سے چھوڑ دیاجائے گااوران قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی یعنی یاجوج ماجوج کوگمراہ کرکے لڑائی کے لئے جمع کرنے کو نکلے گا.‘‘یہاں پرہزاربرس سے مراد ہجری کے ہزار برس ہیں.یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزارسال بعدشیطان اپنی قید سے چھوٹے گا.چنانچہ ایسا ہی ہواکہ ۱۶۱۱ء میں ہندوستان میں مغربی اقوام کے قدم جم گئے اوریاجوج کی ترقی کا زمانہ شروع ہوا.(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ India) حزقیل باب ۳۸و۳۹ اورمکاشفات کوملاکر پڑھاجائے تویہ نتیجہ نکلتاہے کہ ان کی ترقی توسولہویں صدی میں شروع ہوگی (مکاشفات)اور تمام دنیا پرغالب ہوجانا اور تمام ملکوں پرچھا جانا آخری دنوں میں ہوگا(حزقیل باب ۳۸ آیت ۸.۱۶) میں اوپر اشارہ کرآیا ہوں کہ ذوالقرنین کے حالا ت کے مشابہ حالات آخر ی زمانہ میں بھی ایک مثیل ذوالقرنین کے لئے مقدر ہیں اوراس واقعہ کو قرآن کریم میں بطورپیشگوئی بھی بیان کیاگیاہے.اس تفصیلات کے لئے دیکھو بانی سلسلہ احمدیہ کی کتاب (براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ ۹۰تا۹۷طبع اول).
Page 618
اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْۤ (تو)کیا (یہ سب کچھ دیکھ کر )پھر(بھی)و ہ لو گ جنہوں نے کفر(کاطریق )اختیار کیا ہے (یہ)سمجھتے ہیں کہ و ہ مجھے اَوْلِيَآءَ١ؕ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا۰۰۱۰۳ چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بناسکیں گے ہم نے (تو)کافروں کی ضیافت کے لئے جہنم کوتیار کررکھا ہے حلّ لُغَات.نُزُلًا اَلنُّزُلُ:مَاھُیِّئَ لِلضَّیْفِ.مہمانی(اقرب) تفسیر.یہ ان ہی لوگوں کا ذکر ہے جوحضرت مسیح ؑ کو نجات دہندہ اورخدا کابیٹامانتے ہیں.جن کاابتدائے سورۃ میں ذکرآیاتھا.اوراس آیت سے ظاہر ہوگیا کہ اوپر کی آیات میں مسیحیو ںکا ہی ذکر تھانہ کہ کسی اورقوم کا.قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًاؕ۰۰۱۰۴اَلَّذِيْنَ ضَلَّ تو(انہیں)کہہ(کہ)کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے آگاہ کریںجواعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹاپانے سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ والے ہیں.(یہ وہ لوگ ہیں )جن کی (تمام تر)کوشش اس ورلی زندگی میں ہی غائب ہوگئی ہے.اور(اس کے يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا۰۰۱۰۵ ساتھ )و ہ(یہ بھی)سمجھتے ہیں کہ وہ اچھاکام کررہے ہیں.حلّ لُغَات.صُنْعًا اَلصُّنْعُ کے معنے ہیں اَلْعَمَلُ.کام.اَلْاِحْسَانُ.احسان.اِیْجَادُ شَیْءٍ مَسْبُوْقٍ بِالْعَدَمِ.غیرموجود چیز کی ایجاد کی (اقرب) تفسیر.یعنی دنیا کونفع پہنچانے کے لئے ایجادات کرناہی اپنی زندگی کامقصد سمجھتے ہیں دین کی طرف توجہ نہیں.بلکہ اُسے فضول سمجھتے ہیں.
Page 619
اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ لِقَآىِٕهٖ فَحَبِطَتْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نشانوں کا اوراس سے ملنے کاانکا رکردیاہے.اس لئے ان کے (تمام ) اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا۰۰۱۰۶ اعمال گرکر(اسی دنیامیں)رہ گئے ہیں.چنانچہ قیامت کے دن ہم انہیں کچھ بھی وقعت نہیں دیں گے.تفسیر.یعنی ان کی بنائی ہوئی چیزوںکانام و نشان باقی نہ رہے گااورہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے.کیونکہ ان کے تمام اعمال دنیا کے لئے تھے نہ کہ آخرت کے لئے.ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَ اتَّخَذُوْۤا اٰيٰتِيْ یہ ان کابدلہ یعنی جہنم اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے کفر(کاطریق )اختیارکیا اور میرے نشانوںاور میرے رسولوں وَرُسُلِيْ هُزُوًا۰۰۱۰۷ کو(اپنی )ہنسی کا نشانہ بنالیا.تفسیر.ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ.یعنی ان کے کاموں کا اُخروی بدلہ نہ ملنا کوئی سزانہیں بلکہ ان کی مناسب جزاہے.جب وہ خدا تعالیٰ کی خاطرکوئی کام نہ کرتے تھے تواخروی جزاء یادینی بدلہ کی امید انہیں کس طرح ہوسکتی ہے.جَھَنَّمُ جَزَاؤُھُمْ کاعطف بیان ہے اورمراد یہ ہے کہ جزاء سے ہماری مراد جہنم ہے اوریہ جزاء ان کے کفراوراللہ تعالیٰ کے نشانات اوراس کے رسولوں سے ہنسی ٹھٹھے کی وجہ سے ہو گی.یعنی ان قوموں کی نگاہ میں الٰہی کلام اوراس کے رسولوں کی کوئی عزت نہ ہوگی ایک انسان کوخدابناکر سب نبیوں پر ہنسی اور تمسخر کریں گے.چنانچہ دیکھ لو کہ مسیحی لوگ مسیح کوخدا کابیٹاقرار دینے کی وجہ سے سب انبیاء کی سخت ہتک کرتے ہیں اوران کے وجود کولغواور فضول قرار دیتے ہیں اورشریعت کولعنت بتاتے ہیں.
Page 620
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ جولوگ ایما ن لائے ہیں اورانہوں نے نیک(اورمناسب حال)عمل کئے ہیں ان کاٹھکانا یقیناً فردوس کے بہشت الْفِرْدَوْسِ نُزُلًاۙ۰۰۱۰۸خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا۰۰۱۰۹ ہوںگے (وہ)ان (ہی)میں رہاکریں گے(اور)ان سے الگ ہونانہیں چاہیں گے.حلّ لُغَات.فِرْدَوْس فِرْدَوْسٌ کے معنے ہیں اَلْجَنَّۃُ الَّتِیْ تَنْبُتُ ضُرُوْبًا مِنَ النَّبْتِ.وہ باغ جوکئی قسم کی نباتات اُگاتاہے.اَلْبُسْتَانُ یَجْمَعُ کُلَّ مَایَکُوْنُ فِی الْبَسَاتِیْنَ.و ہ باغ جس میں تمام وہ اشیاء ہوں جوباغوں میں ہوسکتی ہیں (اقرب) حِوَلًا اَلْحِوَلُ.اَلزَّوَالُ وَالْاِنْتِقَالُ.علیحدہ ہونا.الگ ہونا.(اقرب)پس لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا کے معنے ہوں گے.کہ وہ اس سے علیحدہ ہونانہیں چاہیں گے.تفسیر.جب ان پرعذاب آئے گاتومومنوںکی ترقی کا وقت شروع ہوگااوان کے صبرکابدلہ ان کومل جائے گا اوراللہ تعالیٰ کے لئے اوراس کے دین کے لئے قربانیوںمیں ان کوایسی لذت محسوس ہوگی کہ باوجود مال اورجان کی قربانیو ں کے و ہ اپنی حالت کو بدلنا پسند نہ کریں گے بلکہ اس ’’ٹوٹی ہوئی سفینہ‘‘میں ہی سفرکرنے میں ساری لذت محسوس کریں گے اوراسے چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوں گے.قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ تو(انہیں )کہہ (کہ )اگر(ہرایک )سمندرمیرے رب کی باتوں(کے لکھنے )کے لئے روشنائی بن جاتا تومیرے اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَ لَوْ جِئْنَا رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے (ہرایک )سمندر(کاپانی)ختم ہوجاتا.گو(اسے )زیادہ کرنے کے لئے ہم
Page 621
بِمِثْلِهٖ مَدَدًا۰۰۱۱۰ اتنا(ہی )اور(پانی سمندرمیں ) لاڈالتے.حل لغات.مِدادًامِدَادًاکے معنے ہیں اَلنِّقْسُ.سیاہی.روشنائی (اقرب) تفسیر.یعنی وہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ یہ ایجادات کی ہیںاوراتنے علوم دریافت کئے ہیں اورکائنات کاراز دریافت کر نے کے قریب ہیں.فرماتا ہے.اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم توان سے کہہ دے (یعنی اس زمانہ کے محمد رسول اللہ صلعم کے اتباع ان سے یوں کہہ دیں )کہ تمہارارازکائنات کودریافت کرنے کی کوشش کرنا ہمیشہ روزاول ہی رہے گااورباوجوداس قدر کوششوں کے تم کولہوکے بیل کی طرح وہیں کے وہیں کھڑے رہوگے اوروہ قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں پیداکی ہیں.ان میں سے اس قدربھی دریافت نہ کرسکو گے کہ جس قدرسمندر کے مقابل پر ایک قطرہ کی حیثیت ہوتی ہے.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ تصانیف کا زمانہ ہوگااوریہ قومیں سائنس پرکثرت سے کتابیں لکھیں گی.قُلْ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰۤى اِلَيَّ اَنَّمَاۤ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ تو(انہیں )کہہ(کہ )میں صرف تمہار ی طرح کاایک بشرہوں (فرق صرف یہ ہے کہ )میری طرف (یہ)وحی وَّاحِدٌ١ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا (نازل) کی جاتی ہے کہ تمہارامعبود ایک ہی (حقیقی)معبود ہے.پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتاہو وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًاؒ۰۰۱۱۱ اسے چاہیے کہ نیک (اورمناسب حال) کام کرے.اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کو (بھی)شریک نہ کرے تفسیر.ان سب پیشگوئیوں اورعلوم غیبیہ کے بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) توان سے کہہ دے کہ میں تواس قدرعلوم سماویہ کے بتانے کے بعد بھی نہیں کہتاکہ میں خدا کابیٹاہوں یاخدائی صفات
Page 622
میر ے اندرہیں.میں توصرف ایک بَشَر ہو ںجس کی ساری خوبی یہ ہے کہ اس پراس کے رب نے اپناکلام نازل فرمایا ہے.پس اگر تم بھی ان انعامات کو حاصل کرناچاہتے ہو توآئومیر ی طرح موحد ہوجائو.اوراللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرو.اورشرک چھو ڑدو.پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تم پر فضل کرتاہے.اورغیب کے خزانے تمہارے لئے کھولتاہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا ہے کہ جوکہف کی آخر ی دس آیات پڑھتاہے دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا(مسند احمد بن حنبل مسند بقیۃ حدیث ابی الدرداء).یہ بھی اس امرکاثبوت ہے کہ دجّال اور یاجوج ماجو ج سے مراد مسیحی فتنہ ہے.کیونکہ ان آیات میں اسی قوم کا ذکر ہے.جیساکہ ہرانسان جو ان آیتوں کو سمجھ کرپڑھے معلوم کرسکتاہے.تَـمَّتْ بِالْخَیْر خ خ خ خ خ