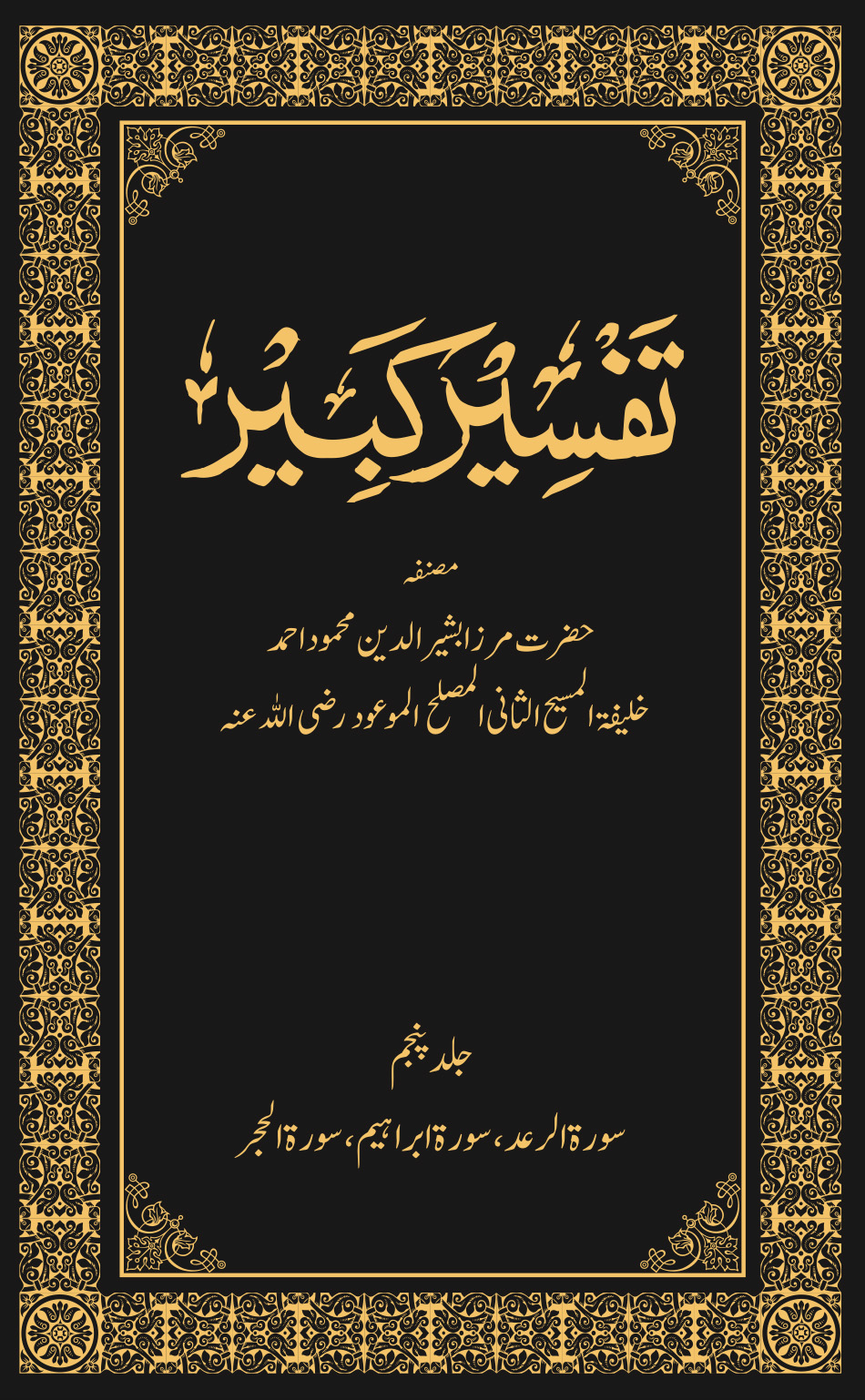Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 5
Content sourced fromAlislam.org
Page 5
سُوْرَۃُ الرَّعْدِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ ر عد.یہ سورۃ مکی ہے.وَھِیَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ اَرْبَعٌ وَّ اَرْبَعُوْنَ اٰیَةً وَ سِتَّةُ رَکُوْعَاتٍ اور بسم اللہ سمیت اس کی چوالیس آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں سورۃ کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف سورۃ رعد کی نسبت حسن ،عکرمہ ،ابن جبیر کی تحقیق ہے کہ یہ ساری مکّی ہے.عطاء کا قول ہے کہ سب مکّی ہے.سوائے وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا والی آیت کے.بعض اور علماء کے نزدیک سب مکّی ہے سوائے هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ والی آیت کے جو لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ والی آیت تک ختم ہوتی ہے.قتادہ سے بھی ایک روایت میں ہے کہ سب سورہ مکی ہے سوائے وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا والی آیت کے.حضرت علیؓ سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ مکی ہے لیکن کلبی مقاتل اور ابن عباسؓ کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے اور قتادہ سے بھی ایک روایت میں اس کا مدنی ہونا مروی ہے.قاضی منذر بن سعد کی بھی یہی تحقیق ہے حضرت ابن عباسؓ تین آیتوں کو بیچ میں سے مکی قرار دیتے ہیں.(۱و۲) وَ لَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ سے شروع کرکے دو آیتیں اور (۳) وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.الآیۃ.سورۃ کے مضامین اس کے مکی ہونے پر دلالت کرتے ہیں عام محققین کا رجحان اس کے مکی ہونے کی طرف ہی ہے.اور اس کے مضامین اس کے مکی ہونے پر ہی دلالت کرتے ہیں.مدنی ہونے کا خیال پیدا ہونے کی وجہ اور غالباً اس کے مدنی ہونے کا خیال اس کی بعض آیتوں کی وجہ سے جو مدنی ہیں پیدا ہوا ہے.اس کے بارہ میں اکابر صحابہ میں سے صرف ایک کی شہادت ہے یعنے حضرت علی کی.اور وہ اسے مکی قرار دیتے ہیں.پس جبکہ اس کے مضامین بھی اس امر کے مؤید ہیں اس کا مکی ہونا یقینی ہے.حضرت ابن عباسؓ چونکہ رسول کریمؐ کے زمانہ میں بچے تھے ان کی رائے حضرت علی کی شہادت کا مقابلہ نہیں کرسکتی.اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق یہ ہے کہ سورۃ یونس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے زمانہ میں دنیا کو دو طرح ہدایت کی طرف لاتا ہے.(۱) سزا سے اور (۲) رحم سے.اس کے بعد سورہ ہود میں سزا کے پہلو پر زور دیا اور سورہ یوسف میں رحم کے پہلو پر روشنی ڈالی گئی.اس سورۃ میں اس امر پر بحث
Page 6
کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کا اعلان جو پہلی تین سورتوں میں کیا گیا ہے وہ کس رنگ میں پورا ہوگا؟ کون سے ذرائع سے کام لے کر دوسرے مذاہب پر اور اپنی قوم پر ان کو غلبہ دیا جائے گا؟ سورۃ کے مضمون کا خلاصہ اس سورۃ کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ غیرمرئی سامانوں سے کام لیتا ہے.انسان کو علم صرف نتائج کے ظہور پر ہوتا ہے.بظاہر ایک ہی قسم کی زمین ہوتی ہے اور ایک ہی قسم کا پانی مگر پھل مختلف ہو جاتے ہیں.پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر قیاس نہ کرو.اس کی کامیابی پر تعجب نہ کرو.اس کی کامیابی قابل تعجب نہیں بلکہ ایسے وقت میں رسول نہ آتا تو قابل تعجب ہوتا.پھر بتایا کہ کامیابی کیسے ہوگی اور دشمنوں کی تباہی کیسے؟ اور بتایا کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی.بڑے بڑے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت واپس لے لے گا.ا ور ان کا رعب جاتا رہے گا.قوانین قدرت اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں وہ قانون قدرت کے ہر ایک شعبہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں لگا دے گا.تم جن کو پوجتے ہو وہ بے بس ہیں.وہ تمہاری نصرت نہ کریں گے.اس کو ایسی روحانی طاقتیں ملی ہیں کہ یہ اکیلا ہی جیت سکتا ہے.جیسے ایک بینا بہت سے اندھوں پر غالب آجاتا ہے.اس کی توحید کی تعلیم کے مقابلہ میں تمہارے شرک کی تعلیم کیسے ٹھیر سکتی ہے؟ جس طرح کہ سیلاب یا پگھلے ہوئے سونے چاندی پر جھاگ بالا بالا دکھائی دیتی ہے اور نادان خیال کرتا ہے کہ شاید یہ جھاگ ہی جھاگ ہے وہی حال آپ کے دشمنوں کا ہے وہ اوپر کی جھاگ کو دیکھتے ہیں نیچے کے سیلاب یا سونے کو نہیں دیکھتے حالانکہ قانونِ قدرت کے مطابق جھاگ ضائع ہوجانے والی چیز ہے آخر پانی یا سونا ہی رہ جاتا ہے.پس ظاہری اور سطحی باتیں دیر تک نہیں رہ سکتیں.اس کی ٹھوس اور مفید تعلیم ہی باقی رہ جائے گی.اس کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے اور آہستہ آہستہ طبعی مناسبتوں کی وجہ سے فطرتیں اسی کو قبول کریں گے.نیز اس تعلیم پر عمل کرنے والے اور اس کے رد کرنے والوں کی حالتوں میں فرق دیکھ کر بھی لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی.سورۃ کا نام نیز قرآن کریم کے ذریعہ سے زبردست معجزات دکھائے جائیں گے اور دل فتح کئے جائیں گے.ظاہری نشانات بھی ہوں گے اور باطنی بھی.ان ظاہری نشانوں میں سے ایک یہ نشان بتایا کہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے اپنے ملک سے نکال دیں گے اور آخر تلوار کی نوبت پہنچے گی.پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوں گی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ملنا شروع ہوگا اور آخر فتح مکہ پر اس جنگ کا خاتمہ ہوگا.یہ سب معجزات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے نہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طاقت سے.خدا تعالیٰ زبردست حملوں سے آپؐ کی سچائی کو ظاہر کردے گا اور اپنے سچے دین کو قائم.اس مضمون کی مناسبت کی وجہ سے اس سورۃ کا نام رعد رکھا گیا ہے.گویا
Page 7
یہ برسنے والا بادل جو آیا ہے اس کے ساتھ کڑک بھی چاہیے تھی.سووہ بھی آگئی ہے.ویری کا ایک غلط خیال رومن اردو قرآن کے مصنف ریورنڈ ویری صاحب لکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں معجزات نہ دکھانے کی اس قدر معذرتیں آئی ہیں کہ اس کا نام بجائے رعد کے معذرتوں والی سورۃ ہونا چاہیے(A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry chapter xiii).میں کہتا ہوں کہ اس سورۃ میں اس قدر انذاری پیشگوئیاں ہیں کہ رعد اس کا طبعی نام ہے.سورۃ رعد اور پہلی تین سورتوں کے ابتداء میں فرق ، کتاب کو بغیر صفت کے بیان کرنے کی وجہ سورہ یونس کے شروع میں کتاب کی صفت حکیم بیان فرمائی تھی.سورہ ہود میں فُصِّلَتْ سورہ یوسف میں مُبِیْن اور اس جگہ بغیر کسی صفت کے کتاب کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یونس میں انذار و تبشیر دونوں پہلوؤں کو یکجا لیا گیا تھا اور بتایا تھا کہ حکیم خدا اپنی حکمتوں کے ماتحت موقع کے مطابق سلوک کرتا ہے.سورہ ہود میں سزا کے پہلو پر زور تھا.اس لئے فُصِّلَتْ اس کی آیات کی صفت بیان ہوئی.کیونکہ تفصیل پھاڑنے اور جدا کرنے کے معنوں پر مشتمل ہے.سورہ یوسف میں ایک طرف غلبہ کے فوراً نہ حاصل ہونے کی حکمتوں کا بیان دوسری طرف عفو اور صلح پر زور تھا.اس لئے مُبِیْنٌ کہا جو عذرومعذرت پر دلالت کرتا ہے.اَلْکتَابُ کے معنی یا تو کامل کتاب کے ہیں یا پہلی سورتوں کی طرف اشارہ ہے سورہ رعد میں چونکہ ذرائع حصول مطالب پر بحث تھی اس لئے بغیر صفت کے رکھا جس کی وجہ سے اَلْکِتٰبُ کے معنے یا تو کامل کتاب کے ہو گئے یا پہلی تین سورتوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ تین صفات جو پہلی تین سورتوں میں بتائی گئی تھیں وہ پورے طور پر اب اس سورۃ کے ذریعہ سے ظاہر کی جائیں گی.
Page 8
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ میں اللہ (تعالیٰ)کا نا م لے کر( شروع کرتا ہوں) جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.الٓمّٓرٰ١۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ١ؕ وَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ الٓمٓر.یہ کامل کتاب کی آیات ہیں.اور جو (کلام) تجھ پرتیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ بالکل حق ہے.رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ۰۰۲ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.حلّ لُغَات.تِلْکَ اٰیٰتٌ اور اَلْکِتٰبُ کی تشریح کے لئے دیکھو سورہ یونس آیت ۲اور ربّ کے معنوں کے لئے دیکھو سورہ یونس ۴.تِلْکَ.اسم اشارہ ہے.اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے.آیاتٌ.آیَۃٌ کی جمع ہے.جس کے معنی علامت، نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں.قرآن کریم کے ہر اک ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہو آیَۃٌ کہتے ہیں (تاج).آیت کی وجہ تسمیہ میرے نزدیک قرآنِ کریم میں وارد فقروں کا نام آیَۃٌ اسی حکمت سے رکھا گیا ہے کہ تا لوگ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے مضامین میں مکمل ترتیب ہے اور ہر فقرہ دوسرے فقرہ کے معانی کے لئے بطور دلیل ہے.بغیر اس کے مدنظر رکھے مطلب پوری طرح نہیں سمجھ میں آسکتا.دوسرے اس لئے بھی کہ ہر ہر ٹکڑا خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے.عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے معجزات کا دعویٰ نہیں کیا.حالانکہ قرآن کریم تو اپنے ہر فقرہ کا نام آیت رکھ کر اسے معجزات پر مشتمل بلکہ خود معجزہ قرار دیتا ہے.اَلْکِتَابُ.مَصْدَرٌ یہ لفظ دراصل کتب کی مصدر ہے.کَتَبَ الْکَتِیْبَۃَ جَـمَعَھَا.لشکر کو جمع کر لیا.کَتَبَ السِّقَآءَ.خَرَزَہٗ بِسَیْرَیْنِ.چمڑے کیتنیوں کے ساتھ اسے سی دیا(تاج ).انہی معنوں کی رو سے کتاب کتاب کہلاتی ہے.کیونکہ اس میں مضامین کو جمع کر دیا جاتا ہے اور مختلف اوراق کو ایک جگہ اکٹھا کرکے سی دیا جاتا ہے.کتاب۱ کے معنی اس خالی کاغذوں کے مجموعہ کے بھی ہوتے ہیں جس پر کچھ لکھا جائے اور کتاب۲ تحریر کو بھی کہتے ہیں اور کتاب۳ کے معنی فرض اور حکم اور اندازہ کے بھی ہوتے ہیں اور کتاب۴ خط کو بھی کہتے ہیں.(اقرب)
Page 9
اَلرَّبُّ.مالک، آقا یا مطاع مستحق یا صَاِحبُ الشَّیءِ یعنی کسی چیز والا.رَبَّ الشَّیْءَ.جَمَعَہٗ اس چیز کو جمع کیا مَلَکَہٗ اس کا مالک ہوا.اَلْقَوْمَ سَاسَھُمْ وَکَانَ فَوْقَھُمْ قوم پر حکومت اور سیاست کی.النِّعْمَۃَ.زَادَھَا نعمت کو بڑھایا.اَ لْاَمْرَ.اَصْلَحَہٗ وَاَتَمَّہٗ کام کو درست اور مکمل کیا.الدُّھْنَ.طَیَّبَہٗ واَجَادَہٗ.تیل میں عمدگی اور خوبی پیدا کی.الصَّبِیَّ.رَبَّاہ حَتّٰی اَدْرَکَ بچہ کی تربیت کی حتیٰ کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا.(اقرب) تفسیر.پہلی سورتوں کے مقطعات اور اس سورۃ کے مقطعات میں فرق (المر) پہلی تینوں سورتوں کے شروع میں الر تھا.اس سورہ کے شروع میں ان تینوں حروف میں میم زائد کر دیا گیا ہے.جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا مضمون پہلی تین سورتوں سے کسی قدر مختلف ہو گیا ہے.جیسا کہ سورہ یونس کے شروع میں حروف مقطعات کی بحث میں بتایا گیا ہے.الٓمّرٰ کے معنی م اعلم کا قائم مقام ہے.پس ان حروف کے معنے یہ ہوئے میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا اور دیکھنے والا ہوں.گویا دیکھنے کی صفت کے ساتھ علم کی صفت کو شامل کر دیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ اور انسان کے متعلق دیکھنے کے لفظ کے استعمال میں فرق یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کے متعلق جب دیکھنے کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد رنگ اور طول و عرض کا نظر آنا ہوتا ہے اور جاننا زیادہ وسیع ہوتا ہے.کیونکہ ناک سے کان سے چھونے سے جن چیزوں کا پتہ لگتا ہے ان کے لئے بھی جاننے کا لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح دیکھی ہوئی چیزوں کے متعلق مگر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آنکھوں اور دوسرے حواس سے بے نیاز ہے اس کے متعلق جاننے اور دیکھنے کے الفاظ کن معنوں میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے مجازاً استعمال ہوتے ہیں اس لئے انسانی استعمال پر ان کا قیاس کرلینا چاہیے.پس جس طرح انسان کے لئے دیکھنے کا لفظ ایک محدود ظہور کے موقع پر بولا جاتا ہے اور جاننا باریک محسوسات کے لئے بھی.اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ رؤیت کا لفظ بولتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ دیکھتا ہے اور جن چیزوں کو انسان دوسرے حواس یا شعور سے محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مکمل طور پر انہیں جانتا ہے.پس گو خدا تعالیٰ کے لئے سب چیزوں کا علم یکساں ہے مگر اس جگہ یہ دو لفظ انسان کی رؤیت اور اس کے علم کے مقابل پر استعمال ہوئے ہیں یعنی ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں انسان دیکھتا ہے اور ان کو بھی جن کو دوسرے حواس سے جانتا ہے خواہ ظاہری ہوں یا باطنی.تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِکے معنے تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ.یعنی وہ آیات جو اس سورۃ یا قرآن کریم میں مذکور ہیں اس موعود
Page 10
کتاب کا حصہ ہیں جس کی نسبت سب دنیا کے ذہنوں میں انتظار چلا آرہا تھا.یا اس کامل کتاب کی جس کی خبر پہلے دی جاچکی ہے.اس لئے تم اس کے مقابلے پر کامیاب نہیں ہوسکتے.کیا جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ ہر نبی کی معرفت خبر دیتا چلا آیا ہے آج وہ اس کو یونہی چھوڑ دے گا.یا اس کے کمالات کے مقابلہ میں تمہارے غلط دعوے ٹھیر سکیں گے؟ وَالَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ....الْحَقُّکی تشریح وَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ.....الْحَقُّ.فرماتا ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں.آخر ہوکر رہنے والی ہیں.انہیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی.ساری آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی جستجو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے صحیح علم حاصل ہو جائے لیکن ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جب وہ کتاب انہیں ملی جو سب شبہات سے پاک ہے تو یہ اس پر ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں اور یقین کو چھوڑ کر شکوک میں مبتلا ہیں.اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اللہ (تعالیٰ) وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونون کے بغیر بلند کیا ہے جو تمہیں نظر آتے ہوں (اور) پھر وہ عرش پر اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ١ؕ كُلٌّ قائم ہواہے اور سورج اور چاند کو اس نے بغیر مزدوری کے( تمہاری) خدمت پر لگایا ہے (چنانچہ) ہر ایک (سیارہ) يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى١ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ ایک معین میعاد تک (اپنی مقررہ گردش کے مطابق) چل رہا ہے وہ ہر امر کا انتظام کرتاہے (اور) وہ (اپنی) آیات کو لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ۰۰۳ کھول کر بیان کرتاہے تاکہ تم (لوگ) اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھو.حلّ لُغَات.عَمَدٌ.عِمَادٌ کی اسم جمع ہے اور اَلْعِمَادُ کے معنی ہیں مَایُسْنَدُ بِہٖ.وہ چیز جس پر سہارا لیا جائے.اَ لْاَ بْنِیَۃُ الرَّفِیْعَۃُ اونچی اونچی بلند دیواروں اور عمارتوں کو بھی عِمَاد کہتے ہیں.(اقرب) سَخَّرَہٗ کَلَّفَہٗ عَمَلًا بِلَا اُجْرَۃٍ.سَخَّرَہٗ کے معنے ہیں کہ اس کو بغیر اجرت یا بدلہ کے کسی کام پر لگادیا.ذَلَّـلَہٗ
Page 11
اس کو مطیع کردیا.وَکُلُّ مَقْھُوْرٍ لَایَمْلِکُ لِنَفْسِہٖ مَایُخَلِّصُہٗ مِنَ الْقَھَرِ فَذٰلِکَ مُسَخَّرٌ.اور ہر وہ شخص جو کسی کے قبضہ میں ہو اور آزاد رہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے مسخر کہتے ہیں.(اقرب) مندرجہ ذیل الفاظ کی تشریح کے لئے حل لغات کے دیگر مقامات کو دیکھئے.رَفَعَ یوسف ۹۷.اَلسَّمٰوٰت.اِسْتَوٰی.اَلْعَرْش یونس۵.اَلْاَجَلُ یونس۱۲.یُدَبِّرُ یونس۴.یُفَصِّلُ یونس۳۸.رَفَعَہٗ رَفْعًا ضِدُّ وَضَعَہُ.رَفَعَ کے معنے ہیں بلند کرنا.زَیْدًا اِلَی الْحَکَمِ رَفْعًا وَرُفْعَانًا قَدَّمَہٗ اِلَیْہِ لِیُحَاکِمَہُ زید کو حاکم کے سامنے مقدمہ کے فیصلہ کے لئے حاضر کیا.اِلَی السُّلْطَانِ رُفْعَانًا.قرّبَہٗ.بادشاہ کے حضور پیش کیا.(اقرب) اَلرَّفْعُ یُقَالُ تَارۃً فِی الْاَجْسَامِ المَوْضُوْعَۃِ اِذَا اَعْلَیْتَہَا عَنْ مَقَرِّھَا وَتَارَۃً فِی الْمَنْزِلَۃِ اِذَا شَرَّفْتَہَا.رَفَع کا لفظ جب اجسام کے لئے استعمال ہو تو کبھی اس کے معنے ان کو ان کی اصل جگہ سے بلند کرنے کے ہوتے ہیں اور کبھی درجہ اور رتبہ میں فضیلت دینے کے.وَاِلَی السَّمَآءِ کَیْفَ رُفِعَتْ.اِشَارَۃٌ اِلَی الْمَعْنَیَیْنِ اِلَی إِعْلَاءِ مَکَانِہٖ وَاِلَی مَاخُصَّ بِہٖ مِنَ الفَضِیْلَۃِ وَشَرَفِ الْمَنْزَلَۃِ چنانچہ آیت اِلَی السَّمَاءِ کَیْفَ رُفِعَتْ میں رفع کے دونوں مذکورہ بالا معنے مراد ہیں.بلندیٔ مکان اور فضیلت و شرف.(مفردات) السَّمٰوٰت.سَمَآءٌ کی جمع ہے.اَلسَّمَآءُ.آسمان.کُلُّ مَاعَلَاکَ فَاَظَلَّکَ.ہر اوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز.سَقْفُ کُلِّ شَیْءٍ وَکُلِّ بَیْتٍ چھت رُوَاقُ الْبَیْتِ برآمدہ.ظَھْرُالْفَرَسِ گھوڑے کی پیٹھ.اَلسَّحَابُ.بادل.الْمَطَرُ بارش.اَلْمَطَرَۃُ الْجَیِّدَۃُ ایک دفعہ کی برسی ہوئی عمدہ بارش.اَلْعُشْبُ سبزہ و گیاہ.(اقرب) اسْتَوٰی اِعْتَدَلَ.اعتدال اختیار کیا.الطَّعَامُ.نَضِجَ پک کر تیار ہو گیا.اَلْعُوْدُ مِنْ اِعْوِجَاجٍ: اِسْتَقَامَکجی دور ہوکر سیدھا اور درست ہو گیا.الرَّجُلُ: اِنْتَھٰی شَبَابُہٗ وَبَلَغَ اَشُدَّہٗ اَوْاَرْبَعِیْنَ سَنَۃً وَاسْتَقَامَ اَمْرَہٗ نشوونما کے کمال کو پہنچ گیا.اپنی جسمانی ترقی کا کمال پالیا.اس کے امور کو درستی حاصل ہو گئی.عَلٰی ظَھْرِ دَآبَۃٍ: اِسْتَقَرَّ قرار پذیر ہو گیا.متمکن ہو گیا.عَلَیْہِ: اِسْتَوْلٰی وَظَھَرَ استیلا اور غلبہ پالیا.لَہٗ وَاِلَیْہِ: قَصَدَ متوجہ ہوا.(اقرب) عَرَشَ.عَرْشًا.بَنٰی بِنَآءً مِنْ خَشَبٍ لکڑی کی عمارت بنائی.اَلْبَیْتَ: بَنَاہُ تعمیر کیا.اَلْکَرْمَ: رَفَعَ دَوَالِیْہِ عَلَی الْخَشَبِ.بیل کو قرینے سے لگائی ہوئی لکڑیوں پر چڑھایا (اقرب) اَلْعَرْشُ سَرِیْرُ الْمَلِکِ اورنگ شاہی.اَلْعِزُّ.عزت و غلبہ.قِوَامُ الْاَمْرِ معاملات اور امور کی درستی کا ذریعہ اور مدار.رُکْنُ الشَّیْءِ سہارا.مِنَ
Page 12
الْبَیْتِ سَقْفُہٗ چھت.اَلْخَیْمَۃُ خیمہ.اَلْبَیْتُ الَّذِیْ یُسْتَظِلُّ بِہٖ سایہ کا کام دینے والا گھر شِبْہُ بَیْتٍ مِنْ جَرِیْدٍ یُجْعَلُ فَوْقَہُ الثُّـمَامُ جھونپڑی (اقرب) اَلْاَجَلُ.مُدَّۃُ الشَّیْءِ وَوَقْتُہُ الَّذِیْ یَحِلُّ فِیْہِ.اَجَل اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام ہونا ہو.کہتے ہیں ضَرَبْتُ لَہٗ اَجَلًا.میں نے اس کے واسطے فلاں کام کے لئے ایک مدت مقرر کر دی ہے.(اقرب) یُدَبّرُ.تدبیر سے فعل مضارع ہے.دَبَّرَالْاَمْرَ: نَظَرَ فِی عَاقِبَتِہِ وَتَفَکَّرَ انجام اندیشی کی اور سوچا.اِعْتَنٰی بِہٖ اس کی طرف توجہ دی اور اس کا اہتمام کیا.رَتَّبَہٗ وَنَظَّمَہٗ ترتیب دی.اَلْوَالِی اَقْطَاعَہٗ: اَحْسَنَ سِیَاسَتَھَا عمدہ نگرانی اور انتظام کیا.اَلْحَدِیْثَ.نَقَلَہٗ عَنْ غَیْرِہٖ بیان کیا.عَلٰی ھَلَاکِہٖ: اِحْتَالَ عَلَیْہِ وَسَعَی فِیْہِ.ہلاک کرنے کی کوشش کی (اقرب) یُفَصِّلُ فَصَّلَ الشَّیْءَجَعَلَہٗ فُصُوْلًا مُتَـمَایِزَۃً کسی چیز یا کسی بات کے کئی حصے قرار دے کر انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرکے دکھایا.اَلْکَلَامَ بَیَّنَہٗ و اضح اور روشن کیا.(اقرب) تفسیر.آیت کے دو معنے اس آیت کے دو معنے ہوسکتے ہیں.ایک یہ کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں اور ایک یہ کہ آسمان بغیر ایسے ستونوں کے کھڑے ہیں جنہیں تم دیکھ سکو یعنے سہارا تو ہے لیکن وہ سہارا تم کو نظر نہیں آتا اور یہ دونوں معنے ہی صحیح ہیں اور آیت کے مفہوم کے مطابق ہیں.اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے کہ ستون عرف عام میں ان مادی ستونوں کو کہتے ہیں جو دوسری چیزوں کا وزن اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں تو آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں اور اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے کہ جس چیز کے ذریعہ سے کوئی چیز اپنی جگہ کھڑی ہے وہ مجازاً اس کا ستون ہے تو پھر آسمانی اجرام ایسے ستونوں پر کھڑے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے جیسے کشش ثقل یا حرکاتِ مخصوصہ.سیارگاں یا اور دوسرے ذرائع جو علماء طبیعیات نے دریافت کئے ہیں یا جو اب تک دریافت نہیں ہوئے.آیت میں کفار کے شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے اس آیت میں کفار کے اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سامان ہیں فتح اور غلبہ کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں میسر نہیں ہیں.پھر وہ کس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہوسکتے ہیں؟ ہر چیز کا سہارا ایک قسم کا نہیں ہوتا اس شبہ کا ازالہ علاوہ پہلی آیت کے مضمون کے کہ جس میں الحق کہہ کر قرآن کریم کے قائم ہونے کی خبر دی گئی تھی اس طرح کیا گیا ہے کہ بے شک چیزوں کا قیام مناسب سہاروں کے اوپر ہوتا ہے مگر یہ ضروری نہیں کہ تمام چیزوں کا سہارا ایک قسم کا ہو مادی اجرام کا سہارا ستون ہوتے ہیں.ایک چھوٹی سی
Page 13
چھت بغیر دیوار یا ستون کے کھڑی نہیں ہوسکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اور صنعت دیکھو کہ کتنے کتنے بوجھل ستارے بغیر کسی ایسی چیز کے جسے عرف عام میں ستون کہہ سکیں یا بغیر کسی نظر آنے والے ستون کے اپنی اپنی جگہوں پر قائم ہیں اور ایک لمبا عرصہ گزرنے پر بھی ان کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا.پس انسانی فعل اور خدائی فعل میں فرق ہے.انسان تو بے شک بغیر ستون کے چھت نہیں کھڑی کرسکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو لاکھوں کروڑوں ستارے بغیر ستونوں کے کھڑے کر چھوڑے ہیں اور ایسے مخفی سہارے ان کے بنائے ہیں کہ جو انسان کو نظر بھی نہیں آتے.اسی طرح روحانی معاملات کو سمجھ لو کہ بے شک انسان جب اپنی کوشش سے غالب ہونا چاہے تو اس کے لئے ظاہری سامانوں کی ضرورت ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو غالب کرنا چاہے تو اس کے لئے ظاہری سامانوں کی ضرورت نہیں اس کے سامان باریک اور غیر مرئی ہوتے ہیں اور اسی وقت حقیقت کھلتی ہے جبکہ نتیجہ نکل آتا ہے اس سے پہلے سب لوگ نبی کے غلبہ کو ناممکن قرار دیتے چلے جاتے ہیں.کفار جن سامانوں کو کامیابی کے لئے ضروری سمجھتے تھے وہ سورۂ بنی اسرائیل رکوع۱۰ میں بیان ہوئے ہیں.اور وہ یہ ہیں (۱) اس کے پاس آدمیوں اور جانوروں کے استعمال کے لئے چشمے ہوں.(۲)باغات کا مالک ہو اور زمینوں کے آباد کرنے کے لئے نہریں کھودے.(۳)اس کے دشمن فوراً برباد کئے جائیں اور پکڑے جائیں.(۴)خدا تعالیٰ اور فرشتے اس کی مدد کے لئے لوگوں کے بالمقابل آکھڑے ہوں.(۵)دولت بے انتہا اس کے پاس ہو.(۶)وہ غیر معمولی طاقتوں کا مالک ہو.آسمان پر لوگوں کے سامنے چڑھ جائے اور وہاں سے لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے جسے لوگ اپنے ہاتھوں میں پکڑ سکیں اور پڑھ سکیں یعنی یہ نہ کہے کہ مجھے زبانی حکم ملاہے بلکہ لکھا ہوا پروانہ جسے لوگ خود پڑھ سکیں اس کے ساتھ ہو.کفار کے نزدیک غلبہ کے دو قسم کے ذرائع دنیوی و دینی ان مطالبات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نزدیک غلبہ کے ذرائع دو قسم کے ہیں.ایک دنیوی یعنی زمینوں مال و دولت پانیوں اور سزا و جزا کی طاقت کا حاصل ہونا.دوسرے دینی یعنی غیر معمولی اور خارق سنت سامانوں کا پیدا ہونا.جیسے کہ خدا تعالیٰ کا ظاہر ہونا، فرشتوں کا ظاہر ہونا، آسمان پر جاکر لکھی ہوئی کتاب کا لے آنا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان دونو قسم کی طاقتوں سے محروم پاتے تھے.ان کے نزدیک بادشاہ کے پاس جو کچھ ہونا چاہیے وہ بھی آپؐ کے پاس نہ تھا.اور ایک نبی کے پاس جو کچھ ہونا چاہیے وہ بھی آپؐ کے پاس نہ تھا.پس وہ خیال کرتے تھے کہ یہ شخص ایک بے ستون اور بے سہارے کی چھت قائم کرنا چاہتا ہے.پس کبھی کامیاب نہیں ہوسکتا.شاید کہا جائے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بادشاہ ہوئے ہیں جو
Page 14
بے حیثیت تھے اور جن کو سامان میسر نہ تھے.جیسے قریب زمانوں میں نادر شاہِ ایران، یا نپولین شاہ فرانس اور ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں.پھر ان لوگوں کے تعجب کی کیا وجہ تھی؟تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ایسے لوگ کبھی کبھی دنیا میں ہوتے رہے ہیں لیکن ان کی ابتدائی حالت میں بھی لوگوں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ وہ اس طرح بادشاہ ہو جائیں گے جب وہ بادشاہ ہو گئے.تبھی لوگوں کی آنکھ کھلی.علاوہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ایسے لوگوں میں بہت بڑا امتیاز تھا.وہ لوگ جب بادشاہ ہو گئے تب انہوں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا.اپنی ابتدائی حالت میں انہوں نے نہ یہ دعویٰ کیا اور نہ ان کو اس امر کا خیال ہی تھا.پس لوگوں میں تعجب پیدا نہیں ہوسکتا تھا.برخلاف اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قبل از وقت دعویٰ کر رہے تھے جس کی وجہ سے عربوں کو اس عجیب دعویٰ پر حیرت ہورہی تھی.مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ جو لوگ ادنیٰ حالت سے بادشاہ بنتے ہیں وہ بادشاہ بننے کے ذرائع اختیار کرتے ہیں.مثلاً نادر شاہ نے ترقی کا ارادہ کیا تو ساتھ ہی کچھ نہ کچھ فوج اپنے اردگرد جمع کرنی شروع کی اور ڈاکے ڈالنے شروع کئے اور پہلے اردگرد کے چھوٹے رؤساء کو زیر کیا پھر بڑے رؤساء کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ ایران کا بادشاہ ہو گیا.یہی حال نپولین کا تھا کہ جہاں ذرہ حرکت دیکھتا بجلی کی طرح کوند کر جا پہنچتا.اور اس طرح اس نے حکومت وقت کو مرعوب کرکے اپنی جگہ لوگوں کے د لوں میں پیدا کرلی اور فوج کی وفاداری حکومت فرانس سے ہٹ کر اس کے ساتھ ہوگئی.تمام ا ن لوگوں کی زندگیوں میں جو ادنیٰ سے اعلیٰ مقامات پر ترقی پاتے ہیں یہ اصول کام کرتا ہوا نظر آتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے اس طرح ترقی کی ان کی زندگیوں میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی.پس اس تجربہ کی بناء پر مکہ کے لوگ آپ کے غلبہ پاجانے اور حاکم ہوجانے کے دعویٰ کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ غلبہ کے سامان یہ کیا جمع کرتا ہے اور جو کچھ ان کو نظر آتا تھا وہ یہ تھا کہ بڑے بڑے بہادروں اور جانبازوں کو آپ نرم دل اور مسکین بنادیتے تھے.بجائے رعب بٹھانے کے اپنے ساتھیوں کو ظلم کی برداشت اور عفو کی تعلیم دیتے تھے کسی پر حملہ کرنا تو الگ رہا جہاں تک ہوسکے دوسرے کے حملہ کو خاموشی سے سہہ لینے کا ارشاد ہوتا رہتا تھا اور یہ تعلیم ایسی تھی کہ ان کے نزدیک اس رستہ پر چل کر بادشاہت کا دروازہ بند ہوتا تھا نہ کہ کھلتا تھا.اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے وہ ان کے ظاہری اعتراضوں کے ساتھ ساتھ ا ن کے سلسلۂ خیالات کو بھی جانتا تھا.جن کے نتیجہ میں یہ اعتراض پیدا ہوتے تھے اور اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ شخص روحانی آسمان کے قیام کا مدعی ہے نہ کہ کسی دنیوی عمارت کا.تمہاری ستونوں والی چھتیں تو آخر گر جاتی ہیں لیکن بغیر ستونوں والا آسمان بے شمار سالوں سے مضبوطی سے کھڑا ہے.اس کے سلسلہ کا بھی یہی حال ہے کہ آسمان کی طرح تمہاری
Page 15
نظروں سے اوجھل سامان جو اندرونی بھی ہیں کہ خود اس تعلیم میں پائے جاتے ہیں جو یہ دیتا ہے اور بیرونی بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی حفاظت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں.پس اس کا سلسلہ ظاہری سامانوں کی احتیاج سے بالا ہے اور انسانی طاقت سے بالا یعنے آسمانی سامانوں پر قائم کیا گیا ہے اور اس پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں.کیونکہ اجرام فلکی کی مادی مثال میں خدا تعالیٰ کی صفات کے اس قسم کے ظہور کی ایک بین دلیل موجود ہے.اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اول دنیا کے اجرام کو بغیر سہارے کھڑا کرکے پھر اپنی صفات کو کامل طور پر ظاہر کرنا شروع کیا اسی طرح اب روحانی دنیا میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے آسمان روحانی کی تکمیل ہوکر صفات الٰہیہ کا کامل ظہور ہوگا اور کامل تعلیم بنی نوع انسان کو دی جائے گی.عرش کے لفظ کا استعمال عرش کا لفظ قرآن کریم میں روحانی یا جسمانی قوانین کی تکمیل کے لئے بولا جاتا ہے اور یہ محاورہ دنیوی نظام سے مستعار لیا گیا ہے.دنیا میں بادشاہ جب کوئی خاص اعلان کرنا چاہیں تو تخت پر سے کرتے ہیں.اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِکے الفاظ صفات الٰہیہ کے کامل ظہور کے لئے آتے ہیں اسی محاورہ کے مطابق قرآن کریم میں صفات اللہ کے کامل ظہور کے لئے اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کے الفاظ آتے ہیں.علّامہ راغب کی عرش کے متعلق بحث باقی رہا یہ کہ عرش الٰہی کیا ہے اور کس قسم کا ہے؟ اس کا عام جواب تو وہ ہے جو علّامہ راغب نے اس لفظ کے معنوں پر بحث کرتے ہوئے دیا ہے وہ لکھتے ہیں وَعَرْشُ اللہِ مَالَا یَعْلَمُہٗ الْبَشَرُ عَلَی الْحَقِیْقَۃِ اِلَّا بِالْاِسْمِ وَلَیْسَ کَمَا تَذْھَبُ اِلَیْہِ اَوْھَامُ الْعَامَّۃِ فَاِنَّہٗ لَوْکَانَ کَذٰلِکَ لَکَانَ حَامِلًا لَہٗ تَعَالٰی عَنْ ذٰلِکَ لَا مَحْمُوْلًا وَاللہُ تَعَالٰی یَقُوْلُ اِنَّ اللہَ یُمْسِکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَکَہُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِہٖ.(مفردات) یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو انسان نہیں جانتا صرف نام جانتا ہے لیکن بہرحال وہ اس قسم کا نہیں جیسا کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں.کیونکہ اگر وہ کوئی تخت کے قسم کی چیز ہو تو اس کے یہ معنے بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو نہیں اٹھایا ہوا.حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہی اٹھایا ہوا ہے.ورنہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی ان کو ان کی جگہ پر نہیں رکھ سکتا.عرش کے لغوی معنے عرش کے لغوی معنے درحقیقت چھت کے ہیں اور تمام معنے اس کے ہر پھر کر چھت کے معنوں
Page 16
کی طرف لوٹ آتے ہیں.تخت کے معنے بھی چھت سے ہی مستنبط ہیں کیونکہ عرش سلطانی بھی تخت کا نام ہوتا ہے اور تخت چند پاؤں پر ایک چھت ڈالنے سے بنتا ہے.غرض عرش کے اصل معنے چھت کے ہیں خواہ سر پر سایہ کے لئے ہو خواہ زمین پر ذرا اونچی کرکے بیٹھنے کے لئے ڈالی جائے.کنایۃً عرش کے معنے علاوہ ان معنوں کے عرش کنایۃً عزت، حکومت، غلبہ اور قوام امر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.(تاج العروس) اور یہ معنی بھی چھت کے لفظ سے ہی نکالے گئے ہیں.کیونکہ پرانے زمانہ میں بڑے لوگ اونچی جگہیں بناکر یا چھت دار کرسیوں یا تختوں پر بیٹھتے تھے.قرآن کریم میں یہ لفظ چھت کے معنوں میں بھی آیا ہے.جیسے فرمایا وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا (البقرۃ :۲۶۰) یعنی گاؤں اپنی چھتوں کے بل گرا ہوا تھا.اورتخت کے معنوں میں بھی آیا ہے جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ (یوسف :۱۰۱) اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا.انہی معنوں میں چار دفعہ سورۂ نمل میں ملکہ سبا کے ذکر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.ان کے علاوہ ۲۱ جگہ اس خاص عرش کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے جس کے معنوں کے لئے دیکھوآیت نمبر۴ سورہ یونس.روح المعانی میں عرش کے معنی حکومت کرنے اور تدبیر امور کرنے کے لکھے ہیں تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کے معنے صرف حکومت کرنے اور تدبیر امور کرنے کے ہیں اور اس کی سند وہ یہ پیش کرتے ہی کہ سورہ یونس میں اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ آتا ہے اور يُدَبِّرُ الْاَمْرَ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کی تفسیر ہے جو معنے یُدَبِّرُ الْاَمْرَ کے ہیں وہی معنے اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ کے ہیں.اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ اور یُدَبِّرُ الْاَمْرَ کے ایک معنی درست نہیں مصنّف روح المعانی نے اس قول کے قائل کا نام نہیں لکھا بعض نئے مفسرین نے بھی ان معنوں کو نقل کیا ہے مگر یہ معنے درست نہیں.اس لئے کہ عرش کا ذکر اس قدر تواتر سے قرآن کریم اور احادیث میں آتا ہے اور ایسے ایسے رنگ میں آتا ہے کہ یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کی مراد عرش سے محض حکومت کرنا ہے بالکل بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے.اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ اور یُدَبِّرُ الْاَمْرَ کے ایک معنی نہ لینے کی وجوہات اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۂ یونس کی آیت میں يُدَبِّرُ الْاَمْرَ جملہ تفسیریہ کے علاوہ اِسْتَوٰی کی ضمیر کا حال اور اِنَّ رَبَّکُمْ کی خبر ثانی بھی بن سکتا ہے اور اس کے یہ معنے ہوسکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر قائم ہوا اس حال میں کہ اس نے تمام نظام عالم کی تدبیر شروع کی یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کئے اور عرش پر قائم ہوا.اور وہ تمام امور کا انتظام بھی کرتا ہے تو
Page 17
یہ معنی اور بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ گو سورۂ رعد کی آیت زیربحث میں بھی یُدَبِّرُالْاَمْرَ کے الفاظ ہیں لیکن اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ کے معاً بعد نہیں بلکہ دوسرے جملوں کے بعد آئے ہیں.پس اس جگہ یہ الفاظ اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کے لئے جملہ مفسرہ نہیں بن سکتے.عرش سے مراد کوئی مادی چیز نہیں غرض اِسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ کے نہ تو یہ معنے ہیں کہ عرش کوئی مادی شئے ہے اور نہ اس سے یہ مراد ہے کہ عرش کوئی چیز ہی نہیں صرف حکومت کے معنوں میں اس لفظ کو استعمال کر لیا گیا ہے.بلکہ اس سے مراد صفات تنزیہہ کا مجموعی نظام ہے جس کے لئے صفات تشبیہہ بطور حامل کے ہیں.یا یوں کہو کہ بطور پاؤں کے ہیں.آسمان وزمین کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے کے ذکر کے بعد پھر عرش پر قائم ہونے کا ذکر یہ بتانے کے لئے کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نیا آسمان زمین تیار کرتا ہے تو اس کی صفات کامل طور پر ظاہر ہوتی ہیں اور کسی ایک صفت کا ظہور نہیں ہوتا.بلکہ صفات تنزیہہ کے مرکز کے تابع جس قدر صفات تشبیہہ ہیں سب کی سب اپنے کام میں لگ جاتی ہیں گویا جس طرح بادشاہ خاص اعلان تخت پر بیٹھ کر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی خاص فیوض صفات تنزیہیہ کے مرکز سے نازل کرتا ہے تا سب صفات تشبیہہ اس کے تابع ہونے کے سبب سے کامل طور پر ظاہر ہونے لگیں اس سے یہ اشارہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کسی ایک صفت کے ذریعہ سے نہ ہوگی.بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو بندے سے تعلق رکھتی ہیں آپ کی تائید میں لگ جائیں گی.پھر فرمایا کہ آسمانوں کے بغیر ستون کھڑے ہونے کے علاوہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سورج چاند کو بغیر کسی اجرت کے تمہارے کام پر لگایا ہوا ہے تمہارے تنخواہ دار نوکر چون و چرا کرسکتے ہیں مگر یہ اجرام فلکی کامل اطاعت سے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں.آخر وہ کون سا ظاہری خوف یا لالچ ہے جو ان کو درست رکھ رہا ہے.خدا تعالیٰ کا ایک قانون ہی ہے نہ وہی قانون اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جاری ہوکر ہر شئے کو اس کے تابع کردے تو اس میں کیا استعجاب ہے؟ پھر فرمایا کہ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ یعنی جس طرح یہ دنیوی قانون جاری ہے اور بغیر بظاہر نظر آنے والے ستونوں کے چل رہا ہے اسی طرح تمہارے دلوں میں یقین اور ایمان پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو جاری کرے گا اور کھلے کھلے نشانات اس کی تائید میں ظاہر کرے گا یا یہ کہ تمام عالم کو اس کی تائید کے لئے واضح احکام دے گا اور عالم کا ذرہ ذرہ اس کی تائید میں لگ جائے گا.
Page 18
وَ هُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْهٰرًا١ؕ وَ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے اور اس میں استحکام کے ساتھ ٹھہرے رہنے والے پہاڑ اور( نیز) دریا بنائے مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ ہیںاور اس میں تمام (اقسام کے) پھلوں سے دونوں قسمیں (یعنی نر ومادہ) بنائی ہیں.وہ رات کو دن پرلا ڈالتا النَّهَارَ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۠۰۰۴ ہے.جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لئے (بلا شک و شبہ) اس (بات) میں کئی نشان (پائے جاتے) ہیں.حل لغات.مَدَّ.مَدَّہٗ.بَسَطَہٗ.مَدَّہٗ کے معنے ہیں اسے پھیلایا.اَلْمَدْیُوْنَ.اَمْھَلَہٗ.اگر یہ لفظ مَدْیُوْ نَ کے ساتھ استعمال ہو تو یہ معنے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈھیل دی.مَدَّ اللہُ عُـمُرَہٗ.اَطَالَہٗ.اس کی عمر لمبی کی.مَدَّالشَّیْءَ.جَذَبَہٗ.کسی چیز کو کھینچا.اَلْقَومَ.صَارَلَھُمْ مَدَدًا.قوم کی مدد کی.وَاَغَاثَھُمْ بِنَفْسِہٖ.اور خود اس کی اعانت کے لئے پہنچا.وَفِی اللِّسَانِ مَدَدَتُّ الْاَرْضَ مَدًّا اِذَا زِدْتَ فِیْہَا تُرَابًا اَوْ سَمَادًا مِنْ غَیْرِھَا.لِیَکُوْنَ اَعْمَرَ لَہَا وَاَکْثَرَ رَیْعًا.لِزَرَعِھَا.لسان العرب میں ہے کہ مَددَتُ الْاَرْضَ اس وقت بولا جائے گا جب اس میں باہر سے کچھ مٹی اور کھاد وغیرہ ڈالی جاوے.تاکہ وہ زمین اچھا غلہ پیدا کرنے لگ جائے.(اقرب) تو معنے یہ ہوئے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور وسیع کیا ہے اور وہ خدا ہی ہے جس نے زمین میں باہر سے لاکر اور مٹی ڈالی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قابل پیدائش بن سکے.یہ بات جغرافیہ سے ثابت ہے کہ اس زمین پر دوسرے کروں کے باریک باریک ذرات پڑ رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ زمین زیادہ پیدائش کے قابل ہورہی ہے اور زمین کی مدد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں غیرمحدود سامان رکھے ہیں تاکہ اس میں رہنے والے تباہ نہ ہوں.الرَّوَاسِی.اَلْجِبَالُ الثَّوَابِتُ اَلرَّوَاسِخُ (اقرب) مضبوط پہاڑ.ان معنوں کے لحاظ رواسی کا مفرد نہیں آتا.تفسیر.مَدَّ الْاَرْضَ میں آسمان اور زمین کے مل کر کام کرنے کی طرف اشارہ ہے مَدَّ الْاَرْضَ میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان و زمین مل کر کام کرتے ہیں.چنانچہ فرمایا رَفَعَ السَّمٰوٰتِ آسمان کو بلند کیا.اور مَدَّ الْاَرْضَ زمین کو نیچے بچھا دیا ہے.مطلب یہ کہ جس طرح یہ دونوں آپس میں زوج ہیں جن کے ملنے سے نتائج پیدا ہوتے ہیں.کل کاروبار زمینی اور آسمانی طاقتوں کے ملنے سے چلتے ہیں اور اسی طرح روحانی عالم کا حال ہے.
Page 19
روحانی زمین اور روحانی آسمان کی ضرورت اس میں بھی ایک روحانی آسمان اور ایک روحانی زمین کی ضرورت ہے.یعنی ایک طرف قبول کرنے والی طبائع کی اور دوسری طرف آسمانی پانی اور آسمانی نور کی ضرورت ہوتی ہے.اور جس طرح آسمانی پانی کے نزول کے بعد قابل زمین اپنے خزانے نکالنے سے رک نہیں سکتی اسی طرح وہ طبائع جو کہ اس روحانی سماء کے لئے بمنزلہ زمین ہوتی ہیں آسمانی پانی کے نزول کے بعد اپنے خزانوں کو روک نہیں سکتے اور جس طرح لوہا مقناطیس کے پیچھے چلا آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیچھے چلے آتے ہیں.پس محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پھیلنے پر تعجب کی بات نہیں.اگر نہ پھیلے تو تعجب ہے کہ اچھی زمین نے عمدہ بارش کے نازل ہونے کے بعد سبزہ کیوں نہیں اگایا؟ ظاہری پہاڑوں اور دریاؤں کی طرح روحانی دنیا میں پہاڑ اور دریا ہوتے ہیں پھر فرماتا ہے زمین میں ہم نے پہاڑ بنائے ہیں جن کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان میں برف جم کر پانی کا ذخیرہ رکھتی ہے اور سال بھر چشموں اور دریاؤں کی صورت میں وہ پانی دنیا کو سیراب کرتا ہے اگر وہ برفوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو چشمے اور دریا بھی بند ہوجائیں اور زمینیں بھی خشک ہو جائیں.یہی حال روحانی دنیا کا ہے.اس میں بھی بعض وجود پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں کہ خدا کے کلام کے لئے ذخیرہ کے طور پر ہوتے ہیں اور بعض وہ وجود ہیں جو فائدہ تو پہنچاتے رہتے ہیں مگر جمع نہیں کرسکتے مگر ایک وہ ہیں جو صرف فائدہ ہی اٹھا سکتے ہیں.انبیاء پہاڑ کی طرح ہوتے ہیں اور علماء نہروں کی طرح پہاڑ تو انبیاء ہیں اور نہریں علماء ہیں اور عام لوگ زمین کی طرح ہیں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں.پس رواسی کو اگراڑا دیا جائے تو پانی نہ رہے گا اور دنیا تباہ ہو جائے گی.ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ.اور تمام پھلوں سے اس نے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے ہیں.گو یہاں صرف پھلوں کا ذکر کیا ہے مگر دوسرے مقامات سے ثابت ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے.یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کے اظہار میں قرآن کریم منفر دہے.عربوں نے سب سے پہلے کھجور کے نر و مادہ کا علم حاصل کیا مگر اس سے زیادہ وہ دریافت نہ کرسکے.قرآن کریم نے بتایا کہ سب پھل دار درختوں کے جوڑے ہیں بلکہ ہر شئے کے جوڑے ہیں.جس وقت یہ سچائی نازل ہوئی دنیا اس کی حقیقت کے سمجھنے سے قاصر تھی.سائنس کی تحقیق کہ ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے مگر اب سائنس تیرہ سو سال بعد اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ تمام اشیاء کے جوڑے ہیں حتیٰ کہ جمادات کے ذرات تک میں نر و مادہ کی دریافت ہورہی ہے.اس مثال سے بھی یہ بتایا ہے کہ جس طرح باقی ہر چیز کو خدا تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے.
Page 20
دماغ کا جوڑا الہام آسمانی ہے اسی طرح انسانی دماغ کا حال ہے.جب تک اس پر خدا تعالیٰ کا نور نازل نہ ہو.اسے صحیح معرفت جو الہام اور عقل کا نتیجہ ہے حاصل نہیں ہوتی.اور اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ جب عقل صحیح اور الہام آسمانی مل جاویں تو انہیں بار دار ہونے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا.پس جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بغیر معرفت الٰہی کا پیدا ہونا ناممکن تھا اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ آپؐ کا لایا ہوا کلام صحیح طریق پر پہنچنے کے بعد انسانی عقول اسے قبول کرنے سے باز رہ سکیں.قرآن کریم کے پھیلنے کی مثال يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ سے ایک اور مثال تعلیم قرآن کے پھیل جانے کی دی.موجودہ تاریکی سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ قرآنی تعلیم کس طرح پھیل سکے گی.جس طرح روحانی دنیا میں تاریکی پھیلی ہوئی ہے.اسی طرح خدا تعالیٰ رات کو دن کے بعد لاتا ہے اگر رات مستقل وجود ہو تو اس کا ہٹنا مشکل ہو لیکن تاریکی کا زمانہ بھی خدا تعالیٰ کے قانون کے ماتحت ہے اور اس کے حکم سے آتا ہے پس جو چیز تابع ہے اس کے متعلق کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ حکم کے باوجود ٹھہری رہے گی.سورج کی ایک شعاع تاریکی کے بادلوں کو پھاڑ دیتی ہے.اسی طرح اب ہوگا.خدا تعالیٰ کے قبضہ میں نور ہی نہیں تاریکی بھی ہے.پس جب وہ چاہے کہ تاریکی ہٹ جائے تو تاریکی قائم نہیں رہ سکتی.جو لوگ فکر کرنے والے ہوں وہ ان مثالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھائیں گے.باقی وہ گروہ جو دوزخ کے بھرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کررہا ہے وہ بے شک رہ جائے گا.وَ فِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّ جَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ اور زمین میں ایک دوسرے کے پاس پاس کئی( اقسام کے) قطعات ہیں.اور کئی( طرح کے) انگوروں کے باغات زَرْعٌ وَّ نَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ اور( کئی قسم کی) کھیتی اور( طرح طرح کے) کھجور کے درخت (جن میں سے بعض) ایک ایک جڑ سے کئی کئی نکلنے وَّاحِدٍ١۫ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ١ؕ اِنَّ فِيْ والے( ہوتے ہیں)اور (بعض) ایک ایک جڑ سے کئی کئی نکلنے والوں کے خلاف( ایک ہی تنے کے ہوتے) ہیں
Page 21
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۰۰۵ جنہیں ایک ہی (طرح کے) پانی سے سیراب کیا جاتاہے.اور( باوجود اس کے) پھل کے لحاظ سے ہم ان میں سے بعض( درختوں) کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں اس میں (بھی) ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں کئی نشان (موجود)ہیں.حلّ لُغَات.قِطَعٌ کا مفرد اَلْقِطْعَۃُ ہے جس کے معنی ہیں اَلْحِصَّۃُ مِنَ الشَّیْءِ.یعنی ساری چیز کا ایک جزو قطعہ کہلاتا ہے.(اقرب) مُتَجَاوِرَاتٌ.تَجَاوَرَ سے ہے اور تَجَاوَرَالْقَوْمُ کے معنے ہیں جَاوَرَ بَعْضُھُمْ بَعْضًا.کہ ایک قوم دوسری قوم کی ہمسایہ بن گئی.(اقرب) وَفِی الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ کے معنی ہیں کہ زمین میں ایسے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے کے آس پاس ہیں.صِنْوَانٌ کا مفرد صِنْوٌ ہے اور اَلصِّنْوُ کے معنے ہیں اَلْاَخُ الشَّقِیْقُ.حقیقی بھائی.اَلْاِبنُ بیٹا.اَلْعَمُّ چچا.وَاِذَاخَرَجَ نَخْلَتَانِ اَوْاَکْثَرُمِنْ اَصْلٍ وَاحِدٍ فَکُلُّ وَاحِدَۃٍ مِنْھُنَّ صِنْوٌ وَصُنْوٌ.اور جب کسی کھجور سے دو یا دو سے زیادہ تنے نکل پڑیں تو ہر ایک کو صنو کہتے ہیں.وَ الْاِثْنَانِ صِنْوَانِ وَصِنْیَانِ مُثَلَّثَیْنِ وَالْجَمْعُ صِنْوَانٌ اور دو کو صِنْوَانِ یا صِنْیَانِ کہتے ہیں اور اس کی جمع صِنْوَانٌ ہے.وَقِیْلَ الصِّنْوُ عَامٌّ فِیْ کُلِّ فَرْعَیْنِ یَخْرُ جَانِ مِنْ اَصْلٍ وَاحِدٍ فِی النَّخْلِ وَغَیْرِہِ.اور بعض کے نزدیک صنو عام ہے.صرف کھجور سے تعلق نہیں رکھتا.پس صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ کے معنے یہ ہوئے کہ ایسے کھجور کے درخت جو دو یا دو سے زائد تنوں والے ہیں.(اقرب) اَلْاُکُلُ.اَلثَّمَرُ.اُکُلْ کے معنی ہیں.پھل.اَلرِّزْقُ الْوَاسِعُ.وسیع رزق.(اقرب) وَنُفَضِّلُ بَعْضُہَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاُکُلِ کے معنے ہوئے کہ ایک کا میوہ اعلیٰ اور زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے کا اعلیٰ بھی نہیں ہوتا اور زیادہ بھی نہیں ہوتا.تفسیر.آنحضرت ؐ کے نبی بن جانے پر ایک لطیف دلیل یعنی یہ نہ سمجھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہی شخص ہے جس طرح یہ عبدالمطلب کا پوتہ ہے اور بھی کئی اس کے پوتے ہیں.پس ان سب کو پیچھے چھوڑ کر یہ کیسے آگے نکل جائے گا؟ زمین کے مختلف حصوں کی مختلف طاقتیں یاد رکھو ایک ہی جگہ کی زمین کی مختلف ٹکڑوں میں مختلف طاقتیں ہوتی ہیں.ایک زمین کے پاس ہی دوسری زمین ہوتی ہے لیکن ایک ٹکڑے میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے اور دوسرے میں نہیں ہوتا.یہ نظارہ کشمیر میں خوب نظر آتا ہے.کہ ایک خاص زمین میں زعفران ہوتا ہے اور بالکل
Page 22
متصل ساتھ ہی کی زمین میں زعفران نہیں ہوتا.اسی طرح صوبہ سرحد میں ایک ٹکڑا زمین کا ہے جسے غالباً باڑہ کہتے ہیں اس میں خاص قسم کے اعلیٰ چاول ہوتے ہیں.پاس کے کھیتوں میں وہ چاول نہیں ہوتے.زمینوں کو چھوڑ کر جانوروں کو لے لو.مشک کا ہرن ایک خاص علاقہ میں اچھا مشک دیتا ہے.وہاں کے پاس ہی دوسرے علاقہ میں لے جاؤ تو پہلے تو مشک ناقص ہونے لگے گا پھر بالکل مشک ہی پیدا نہ ہوگا.تو فرمایا جب مٹی میں ہی ایسے فرق ہو جاتے ہیں تو انسانوں میں کیوں نہیں ایسا فرق ہوسکتا کہ ایک آسمانی بن جائے اور ایک زمینی.یُسْقٰی کے لفظ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ چیزیں باوجودیکہ ان کو ایک ہی پانی ملتا ہے.مختلف رنگ و مزے کی ہوتی ہیں.لیکن تم کو تو پانی بھی علیحدہ علیحدہ قسم کا پلایا جاتا ہے.اس کو آسمانی پانی ملتا ہے اور تم کو تو شیطانی کیونکہ تم تو اس کلام کو سننے سے انکاری ہو اور شیطانوں کی باتیں سنتے رہتے ہو.سامان سے ہر شخص حسب استعداد فائدہ حاصل کرتا ہے يُسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے جیسا آدمی اور ہمارے جیسے ہی سامانوں والا ہم سے آگے کیسے نکل جائے گا ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا ایک ہی پانی پی کر مختلف بیج مختلف مزے نہیں پیدا کردیتے.پس یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامان ایک قسم کے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سامان کو استعمال کرنے کی قابلیت مختلف ہے.ایک تلوار ایک اناڑی کے ہاتھ میں بیکار ہوتی ہے وہی تلوار شمشیر زن کے ہاتھ میں فتح و شکست کی ضامن ہوجاتی ہے.ابوبکرؓ اور عمرؓ انہی مکہ والوں میں سے تھے جب تک ان کے ساتھ رہے معمولی آدمی رہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے دنیا کے بہترین دماغ بن گئے اور دوست و دشمن نے انہیں خراج تحسین دیا اور دے رہے ہیں.وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ اور (اے مخاطب )اگرتجھے (ان منکران حق پر) تعجب آئے تو (وہ بجا ہے کیونکہ) ان کا( یہ) کہنا (کہ) جب ہم خَلْقٍ جَدِيْدٍ١ؕ۬ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ١ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ ( مر کر) مٹی ہوجائیں گے تو کیا ہمیں واقع میں (پھر) کسی نئے جنم میں آنا ہوگا( واقعی) عجیب (قول) ہے.یہ وہ
Page 23
الْاَغْلٰلُ فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ١ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ١ۚ هُمْ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیاہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق (پڑے) ہوں گے اور فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۰۰۶ (یہ لوگ دوزخ کی) آگ (میں پڑنے) والے ہیں وہ اس میں رہا کریں گے.حل لغات.اَلْغُلُّ.طَوْقٌ مِنْ حَدِیْدٍ اَوْقِدٍّ یُجْعَل فِی الْعُنُقِ اَوْ فِی الْیَدِ.غُلّ اس طوق کو کہتے ہیں جو لوہے یا چمڑے کا ہوتا ہے.اور ہاتھ میں یا گردن میں ڈالا جاتا ہے وَمِنْہُ قِیْلَ لِلْمَرْأۃِ السّیِّئَۃِ الْخُلُقِ غُلٌّ قَـمِلٌ.انہی معنوں میں بدخلق عورت کو غُلٌّ قَـمِلٌ کہتے ہیں.وَاَصْلُہٗ اَنَّ الْغُلَّ کَانَ یَکُونُ مِنْ قِدٍّ وَعَلَیْہِ شَعْرٌ فَیَقْمَلُ فِیْ عُنُقِ الْاَسِیْرِ فَیُؤْذِیْہِ فَیَکُوْنُ الْغُلُّ القَمِلُ اَنْـکَی مِنْ غَیْرِہِ.اور اصل اس کی یوں ہے کہ غُلّ ایسے چمڑے سے ہوتا تھا جس میں بال ہوتے تھے اور قیدی کی گردن میں ڈالنے کے بعد اس میں جوئیں پڑ جاتی تھیں اور وہ طوق اسے تکلیف دیتا اس طرح وہ جوؤں والا غل زیادہ تکلیف دِہ ہو جاتا تھا.وَجـمْعُہٗ اَغْلَالٌ وَغُلُوْلٌ.اس کی جمع اَغْلَالُ بھی آتی ہے اور غُلُوْلٌ بھی.اور جب یہ محاورہ بولتے ہیں کہ ھَذَا غُلٌّ فِیْ عُنُقِکَ تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ یہ عمل تیرے گلے کا ہار بن گیا ہے اور تجھ کو اس کے بدلے میں عذاب ملے گا.(اقرب) تفسیر.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی میں اور ان کے ذریعہ سے دنیا کی اصلاح ہونے میں کوئی تعجب کی بات نہیں.آنحضرت ؐ کے مخالفین کا آپ کی ترقی پر تعجب تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا اس قدر خراب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی فکر نہ کرے.یہ امر خلاف سنت ہے کہ آنکھ تو ہو مگر اس سے کام لینے کے لئے روشنی نہ ہو.مادہ تو ہو مگر اس کی طاقتوں کو ظاہر کرنے کے لئے نر نہ ہو پھر تعجب اس امر پر تو ہوسکتا ہے کہ نر و مادہ ملیں مگر نتیجہ پیدا نہ ہو.اس پر کیا تعجب ہے کہ ان دونوں کے ملنے سے بچہ کس طرح ہو گیا؟ پس اس پر تعجب نہ کرو کہ اس کے ذریعہ سے دنیا کی اصلاح کس طرح ہوگی؟ تعجب تو تم کو اپنے اس احمقانہ خیال پر کرنا چاہیے کہ ہم گرنے کے بعد اٹھیں گے کس طرح؟ مرنے کے بعد زندہ کس طرح ہوں گے.جب آسمانی سہارا آجائے جب زندگی کا پانی مل جائے پھر ان باتوں میں کیا تعجب ہے؟
Page 24
اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ١ۚ الآیۃ.اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ مایوسی خدا تعالیٰ کے فضلوں سے کفر اور انکار کی وجہ سے ہوئی ہے.اللہ تعالیٰ کے طریق کو چھوڑ کر خود ساختہ قواعد کی اتباع ناکام کرتی ہے جو لوگ خودساختہ قواعد کی اتباع کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کو چھوڑتے ہیں ان کے لئے مایوسی کا شکار ہوجانا کوئی عجیب بات نہیں.اور مایوسی کا لازمی نتیجہ ناکام ہونا اور حسرتوں کے جہنم میں جلنا ہے.افسوس کہ اس وقت یہی حالت مسلمانوں کی ہے.وہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کو چھوڑ کر خودساختہ علاجوں کی طرف متوجہ ہیں.بجائے اشاعت اسلام اصلاح اخلاق دعا اور انابت اور تسلیم لامراللہ کے سود اور بنک اور انگریزی تعلیم اور بیمہ اور کیا کیا علاج تجویز کررہے ہیں؟ حالانکہ ان میں سے بعض خلاف اسلام اور مضر ہیں اور بعض بغیر روحانی طاقتوں کے غیرمفید ہیں.وَ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ اور وہ نیک جزا پر سزا کو مقدم کرتے ہوئے تجھ سے (اس کے) جلدی (آنے) کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ ان سے مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ١ؕ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ پہلے(ایسے لوگوں پر) تمام( قسم کے) عبرتناک عذاب آچکے ہیں اور تیرا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود( بھی) عَلٰى ظُلْمِهِمْ١ۚ وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ۰۰۷ بلا شک و شبہ (بہت ہی) بخشنے والا ہے اور( اسی طرح) تیرا رب یقیناً سخت سزا دینے والا (بھی) ہے.حلّ لُغَات.اَلْمَثُلٰتُ.اس کا مفرد اَلْمَثُلَۃُ ہے جس کے معنے ہیں.اَلْعُقُوْبَۃُ.سزا.یُقَالُ حَلَّتْ بِہِ الْمَثُلَۃُ اور حَلَّتْ بِہِ الْمَثُلَۃُ کا محاورہ مذکورہ بالا معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے کہ اس پر سزاوارد ہوئی.وَمَا اَصَابَ الْقُرُوْنَ الْمَاضِیَۃَ مِنَ العَذَابِ وَھِیَ عِبَرٌ.یُعْتَبَرُبِھَا.اور گزرے ہوئے لوگوں پر جو عذاب نازل ہوئے اور جو دوسری اقوام کے لئے موجب عبرت ہیں ان کو بھی مَثُلَۃٌ کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اَغلال کو دور نہ کیا اور خدا تعالیٰ کے سامانوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی طاقتوں سے کام نہ لیا تو تم خشک لکڑی کی طرح ہو جاؤ گے.جس کا کام سوائے جلنے کے اور کچھ
Page 25
نہیں.تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا پھر وہ آگ لاؤ جس میں ہم نے جلنا ہے ہم جو نیکی کی بات بتاتے ہیں اس کو تو قبول نہیں کرتے اور جو عذاب کا ڈراوا دیتے ہیں اس کو جلدی مانگنے لگ جاتے ہیں.حالانکہ نبیوں کے ساتھ عذاب بھی آتا ہے اور اب بھی آئے گا.مگر انہیں یہ نہ چاہیے تھا کہ بجائے اصلاح کرکے فضل الٰہی طلب کرنے کے ضد کرکے عذاب طلب کرتے.انبیاء کے دشمن ہمیشہ فضل کے بجائے عذاب ہی کے طالب ہوتے ہیں ہر نبی کے وقت میں ایسا ہی ہوتا ہے ان کے نادان دشمن فضل نہیں مانگتے یہ نہیں کہتے کہ سچا ہے تو ہمیں اس کی اطاعت نصیب ہو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو.انبیاء کے بھیجنے سے لوگوں کو تباہ کرنا مقصود نہیں ہوتا وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ.اس آیت میں اس عظیم الشان حکمت کو بیان فرماتا ہے کہ ہماری غرض انبیاء کے بھیجنے سے لوگوں کو تباہ کرنا نہیں بلکہ انہیں بچانا ہے.دنیا کے لوگ ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں.پھر بھی ہم مغفرت سے کام لیتے جاتے ہیں.پس تمہارے عذاب جلدی مانگنے سے ہم عذاب جلدی نہ لے آئیں گے کیونکہ یہ ہماری سنت کے خلاف ہے.ہماری خواہش تو یہ ہے کہ تم کو بخشش ملے.پس انہی ذرائع کو ہم کام میں لائیں گے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نجات دینے کا موجب ہوں.وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ.مگر اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے.تمہاری اصلاح کی پوری کوشش کی جائے گی لیکن تم نے اصلاح نہ کی تو پھر خدا تعالیٰ سزا بھی ضرور دے گا.اور اس کی سزا کی شدت کا مقابلہ کوئی اور عذاب نہیں کرسکے گا.اللہ تعالیٰ کا عذاب دوسروں کے عذاب سے سخت ہوتا ہے اس جملہ کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ عذاب دینے میں سختی سے کام لیتا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دوسروں کے عذاب سے سخت ہوتا ہے.کیونکہ وہ جن راہوں سے عذاب محسوس کراسکتا ہے انسان نہیں کراسکتے.عِقاب کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب بلا وجہ نہیں ہوتا عِقَاب کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب بلاوجہ نہیں ہوتا.بلکہ انسان کے اعمال کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ عقاب اس چیز کو کہتے ہیں جو ایڑیوں سے لگی ہوئی ہو یعنی اپنے کئے کا نتیجہ ہو جیسے بچہ ماں کے ساتھ لگا ہوتا ہے.
Page 26
وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ١ؕ اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں (کہ) اس( شخص) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍؒ۰۰۸ اتارا گیا(حالانکہ) تو صرف آگاہ اور( ہشیار) کرنے والا ہے اور ہر ایک قوم کے لئے (خدا تعالیٰ کی طرف سے ) ایک راہنما (مقرر) ہے.تفسیر.کفار کے نزدیک نشان سے مراد عذاب ہوتا ہے باوجود بار بار نشانات ظاہر ہونے کے اور آئندہ کے لئے نشانات کی خبر دینے کے کفار کہتے کہ نشان تو کوئی دکھاتے نہیں ہم مانیں کیونکر؟ اور اس نشان سے ان کی مراد عذاب الٰہی کا نزول ہوتا ہے.کیونکہ ان کے نزدیک نشان یہی تھا کہ وہ تباہ ہو جائیں.قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار جب بھی آیت کا مطالبہ کریں جب تک کوئی دوسرا قرینہ اور معنوں پر دلالت نہ کرے ہمیشہ اس کے معنے عذاب کے ہوتے ہیں.اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ.فرمایا.یہ نادان سوچتے نہیں کہ تیرا تو ایک نام منذر ہے.بلکہ نہ ماننے والوں کے لئے تیرا یہی نام ہے.پس جو بات تیرے نام ہی سے بتا دی گئی ہے اب یہ اس کی اور وضاحت کیا چاہتے ہیں؟ مگر ساتھ ہی ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وَلِکُلِّ قَوْمٍ ھَادٍ.ہر قوم کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ مامور بھیجتا ہے.اگر ہدایت سے پہلے عذاب آجائے تو ھاد کی صفت باطل جائے.پس صبر کریں.پہلے یہ ہادی بن جائے.اس کے بعد جو رہ جائیں گے ان کے لئے منذر بن جائے گا.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہا.کچھ عرصہ تک آپؐ کے ذریعہ سے لوگ ہدایت پاتے پھر اس طبقہ کے بچے کھچے لوگ عذاب سے تباہ ہو جاتے.پھر ایک اور طائفہ ہدایت پاتا پھر ان کے سرکردہ عذاب میں مبتلا ہوتے.اسی طرح آخر تک ہوتا چلا گیا.یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے آخری فیصلہ نے تمام غلبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے صحابہ کو بخش دیا.اور آپؐ کے دشمن بالکل تباہ ہو گئے.
Page 27
َللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ اللہ (خوب) جانتاہے اسے (بھی) جو ہر مادہ اٹھاتی ہے اور جسے رحم ناقص کر( کے گرا) دیتے ہیں اور( اسے بھی) مَا تَزْدَادُ١ؕ وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ۰۰۹ جسے وہ بڑھاتےہیں اور ہر چیز ہی اس کے پاس ایک بڑے اندازہ میں موجود ہے.حلّ لُغَات.تَغِیْضُ غَاضَ ماضی سے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے.اور غَاضَ الْمَاءُ غَیْضًا کے معنی ہیں.نَقَصَ.پانی کم ہو گیا.اَوْغَارَ فَذَھَبَ فِی الْاَرْضِ.یا جذب ہو کر زمین کی تہ میں چلا گیا.وَفِی الصِّحَاحِ : قَلَّ فَنَضَبَ اور صحاح میں غَاضَ الْمَاءُ کے یہ معنی کئے گئے ہیں کہ پانی کم ہوکر خشک ہوگیا.ثَـمَنُ السِّلْعَۃِ.نَقَصَ جب غَاضَ کا لفظ ثَمَن کے ساتھ استعمال ہو تو یہ معنے ہوتے ہیں کہ سامان کی قیمت جو پہلے زیادہ تھی کم ہو گئی.وَیُقَالُ غَاضَ الْمَاءَ وَالثَّمَنَ.اور جب غَاضَ کا لفظ متعدّی ہوکر استعمال ہو اور اس کا مفعول اَلْمَآءُ اور اَلثَّمَنُ ہو تو یوں معنے کئے جائیں گے کہ سامان کی قیمت کو گرا دیا اور پانی کو کم کر دیا.وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ.اَیْ مَاتَنْقُصُ تِسْعَۃَ اَشْھُرٍ.پس اقرب الموارد والے نے مَاتَغِیْضُ الْاَرْحَامُ کے معنے یہ کئے ہیں کہ (اللہ خوب جانتا ہے) رحم اپنی مقررہ مدت ولادت میں جو کمی کرتے ہیں.نیز اَلْغَیْضُ جو غَاضَ کا مصدر ہے اس کے ایک معنی لغت میں یہ بھی کئے گئے ہیں اَلسِّقْطُ الَّذِیْ لَمْ یَتِمَّ خَلْقُہٗ.کہ غیض اس بچے کو کہتے ہیں جس کی پیدائش ابھی مکمل نہ ہوئی ہو اور وہ ناقص ہونے کی حالت میں گر جائے.پس غَیْض کے اس معنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ کے معنے یہ ہوں گے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جسے رحم ناقص کرکے گرا دیتے ہیں.(اقرب) تَزْدَادُ.اِزْدَادَ ماضی سے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اِزْدَادَ، زَادَ سے بنا ہے جس کے معنے ہیں زیادہ ہو گیا.یا زیادہ کر دیا.اور اِزْدَدْتُّ مَالًا وَازْدَادَ الْاَمْرُ صُعُوْبَۃً کے معنے ہیں میں نے مال کو بڑھایا اور معاملہ پیچیدگی اور مشکل میں بڑھ گیا.یعنی یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور جب اِزْدَادَ الرَّاھِنُ دَ رَاھِمَ مِنَ الْمُرْتَھِنِ کا محاورہ بولا جائے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ اَخَذَ ھَا زِیَادَۃً عَلٰی رَأْسِ الْمَالِ کہ رہن رکھنے والے نے مُرْتَھِنْ سے اصل مال پر بطور نفع کچھ رقم زیادہ لی.اور جب کوئی چیز دینے والا
Page 28
لینے والے کو کہے ھَلْ تَزْدَادُ تو اس کے معنے ہوتے ہیں ھَلْ تَطْلُبُ زِیَادَۃً عَلی مَااَعْطَیْتُکَ کیا اس کے علاوہ جو تجھے دیا گیا تو اور زیادہ طلب کرتا ہے؟ پس مَاتَزْدَادُ کے معنے یہ ہوں گے کہ (اللہ خوب جانتا ہے) رحم اپنی مقررہ مدت ولادت میں جو زیادتی کرتے ہیں.(اقرب) اَلزِّیَادَۃُ.نیز اَلزِّیَادَۃُ جو زَادَ کا مصدر ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اَنْ یَّنْضَمَّ اِلٰی مَا عَلَیْہِ الشَّیْءُ فِیْ نَفْسِہٖ شَیْءٌ اٰخَرُ.کہ جن عام حالتوں میں کوئی چیز پائی جاتی ہو اس پر بطور زیادتی کوئی اور چیز اس کے ساتھ مل جائے پس ان معنوں کے مدنظر مَاتَزْدَادُ کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے جسے رحم اصل چیز میں بڑھاتے اور زیادہ کرتے ہیں.(اقرب) مقدار کے معنےمیں’’ بڑا‘‘ کا لفظ تنوین کا ترجمہ ہے جو کبھی بڑے کے معنے دیتی ہے.تفسیر.پہلے بتایا تھا کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید مخفی ذرائع سے کریں گے.اسی کے ذکر میں یہ بھی بتایا تھا کہ تمام دنیا میں جوڑے پیدا کئے گئے ہیں.حتیٰ کہ زمین و آسمان بھی گویا ایک قسم کے جوڑے ہیں.ایک اثر ڈالتا ہے اور دوسرا اسے قبول کرتا ہے.ایک مخفی ذرائع سے دوسرے کی حیات کو قائم رکھتا ہے اور دوسرا قائم رہتا ہے.ایسا ہی روحانی سلسلہ میں بعض لوگ نرکا درجہ رکھتے ہیں اور بعض مادہ کا.اول الذکر اثر ڈالتے ہیں اور ثانی الذکر قبول کرتے ہیں.اب فرمایا کہ اس قانون کے ماتحت اب بھی ایک شخص کا ظہور ہوا ہے.جو روحانی طور پر نر کا مقام رکھتا ہے جس سے تعلق کے بغیر کوئی روحانی درجہ حاصل نہیں ہوسکتا.اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى کا مطلب اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى.یعنی ہم جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے اندر کیا رنگ رکھتے ہیں.انہوں نے اپنے اندر کون سے مادہ کو قبول کیا ہے.روحانیت کا یا شیطنت کا.اور یہ کہ کس کا مادہ بڑھے گا اور کس کا گھٹے گا؟ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو قبول کرنے والے ہیں وہ بڑھیں گے اور ان کے اندر اعلیٰ قابلیتیں پیدا ہوں گی.اور جو آپؐ کے مقابل شیطانوں کے اثر قبول کررہے ہیں ان کی ظاہری اور باطنی نسل تباہ ہوگی.مَا تَحْمِلُ سے ظاہری حمل بھی مراد ہو سکتا ہے ظاہری حمل بھی اس جگہ مراد ہوسکتا ہے اور اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی آئندہ نسلیں کیا بننے والی ہیں.آئندہ تمہاری عورتوں کے ہاں وہی اولاد ہوگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ہوگی.آپؐ کی مخالف اولاد ضائع ہی ہو جائے گی.چنانچہ ایسا ہی ہوا.مکہ کی نئی نسل کثرت سے آپؐ کے خدام میں داخل ہوئی.اور بزرگ ان کو دیکھ دیکھ کر جلتے رہے.ان کے ظلم
Page 29
اور قہر نئی نسل کو ایمان لانے سے روک نہ سکے.یہ تدبیر بھی آپؐ کی ترقی کے لئے نہایت ممد ہوئی.گو ابتداء ًاس کو جانچنے کے لئے کفار کے پاس کوئی سامان نہ تھے.عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ۰۰۱۰ وہ غائب اور حاضر (دونوں) کا جاننے والا ہے بڑے مرتبہ والا (اور) بڑی شان والا ہے.حلّ لُغَات.اَلْغَیْبُ.یہ غَابَ.یَغِیْبُ کا مصدر ہے.اور غَابَتِ الشَّمْسُ وَغَیْرُھَا.اِذَا اسْتَتَرَتْ عَنِ الْعَیْنِ.غَابَ کا لفظ سورج کے لئے یا کسی اور چیز کے لئے اس وقت بولتے ہیں کہ جب سورج غروب ہوجاوے.یا کوئی اور چیز آنکھوں سے اوجھل ہوجائے.وَاسْتُعْمِلَ فِیْ کُلِّ غَائِبٍ عَنِ الْحَآسَّۃِ جو بات حواس سے بالا اور پوشیدہ ہو اس پر بھی غیب کا لفظ اطلاق پاتا ہے.اور شہادۃ کا لفظ غیب کے بالمقابل بولا جاتا ہے.(مفردات) غیب اور شہادت کے دو معنی پس غیب اور شہادت کے دو معنی ہیں.(۱) شہادۃ جو لوگ ظاہر کرتے ہوں.اور غیب جسے وہ چھپاتے ہوں.(۲)جو حواس ظاہری سے معلوم ہوسکے وہ شہادت ہے اور جو باتیں حواس سے بالا اور پوشیدہ ہیں، وہ غیب ہیں.تو عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تمہاری ہر ایک تدبیر کو جانتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دشمن کی باتوں کو نہ جانتا ہو لیکن دشمن اس کی باتوں سے واقف ہو تو وہ انسان اس سے مقابلہ نہیں کرسکتا.پس تمہیں احتیاط کرنی چاہیے.اَلْمُتَعَالُ.تَعَالٰی.اِرْتَفَعَ.تَعَالٰی کے معنے ہیں بلند ہوا.وَالْمُتَعَالُ.رَفِیْعُ الشَّانِ.بڑی شان والا.اَلْکَبِیْرُ ذُ وْالْکِبْرِ.کبیر کے معنے ہیں کبر والا.اور کبر کے معنے ہیں اَلشَّرْفُ بزرگی اَلرِّفْعَۃُ فِی الشَّرْفِ.شرف کے لحاظ سے رفعت اَلْعَظْمَۃُ وَالتَّجَبُّرُ.عظمت و جبروت (اقرب) پس کبیر کے معنی ہوں گے بزرگی والا.عظمت و جبروت والا.شرف کے لحاظ سے رفعت والا.کبیر اور مُتَعال میں فرق کبیر اور مُتَعال دونوں میں یہ فرق ہے کہ کبیر اس بڑائی پر دلالت کرتا ہے جس سے دوسروں پر اثر ڈالنے والی بلندی مراد ہو جیسے متکبر ہوتا ہے.یعنی دوسروں کے مقابلہ میں بڑا بننا چاہتا ہے.ایسا ہی کبیر میں خدا تعالیٰ کی وہ بڑائی مراد ہے جو بہ نسبت اس کی مخلوق کے ہے.
Page 30
مُتَعَال اس بڑائی پر دلالت کرتا ہے جو تنزہ والی ہوتی ہے.یعنی اس کی ایسی ارفع شان ہے کہ بندوں سے واسطہ ہی نہیں رہتا.پس جو رفعت استغناء پر دلالت کرتی ہے وہ مُتَعَال کے لفظ سے بیان کی گئی ہے.اور جو رفعت بندوں سے تعلق پر دلالت کرتی ہے اس کو الکبیر کے لفظ سے واضح فرمایا ہے.ان دونوں کے اس جگہ پر ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ ہم کبیر ہیں.تمہاری طاقتیں ہمارے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں.ہم تمہاری مخالف کوششوں کو بالکل ذلیل و حقیر بنا کر بیکار کر دیں گے یعنی جب چاہیں گے پیس ڈالیں گے اور ہم غنی ہیں.تمہاری تباہی سے ہماری حکومت میں کوئی کمی نہ آوے گی.تفسیر.دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کا گر اس آیت میں یہ گر بتایا ہے کہ دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کے لئے اس کی تدابیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے.اگر ہم اس کی کوششوں سے واقف ہیں تو ان کے اثر کو دور کرسکیں گے ورنہ ہر وقت خطرہ میں رہیں گے.عٰلِمُ الْغَيْبِ کہنے کا مطلب عٰلِمُ الْغَيْبِ کہہ کر بتایا کہ اے نادانو! اتنا تو سوچو تمہارا مقابلہ کس ہستی سے ہے.کیا اس خدا سے کہ جو تمہاری تدبیروں کو جانتا ہے اور پھر وہ کبیر ہے.تمہاری تمام تدابیر کو ایک منٹ میں توڑ کر رکھ سکتا ہے.پھر اس کی شان تمہارے علم سے نہایت ارفع ہے.یعنی وہ تمہاری تدابیر کو جانتا ہے اور تم کو علم نہیں کہ وہ تمہارے ہلاک کرنے کے کیا کیا سامان کررہا ہے؟ پس غور کرو کہ کیا تم ایسی ذات کا مقابلہ کرسکتے ہو! کبیر کے لفظ سے ان کی تدابیر کے توڑنے پر دلالت کی ہے.اور متعال سے بتایا کہ تم خدا کی تدابیر سے واقف نہیں ہوسکتے.پھر اسی کی تشریح میں آگے فرمایا.سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهٖ وَ مَنْ هُوَ جو تم میں سے بات چھپاتا ہے اور وہ بھی جو اسے ظاہر کرتا ہے( اس کے علم کے لحاظ سے دونوں) برابر ہیں نیز وہ بھی جو مُسْتَخْفٍۭ بِالَّيْلِ وَ سَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ۰۰۱۱ رات کو چھپ رہتا ہے اور جو دن کو چلتا ہے.حلّ لُغَات.سَارِبٌ.سَرَبَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے.اور سَرَبَ الْبَعِیْرُ سُرُوْبًا کے معنی ہیں تَوجَّہَ لِلرَّعْیِ.اونٹ چرنے کے لئے گیا.( اِبِلٌ سَارِبَۃٌ) مُتْوَجِّہَۃٌ لِلرَّعْیِ.اور اِبِلٌ سَارِبَۃٌ ان اونٹوں کو کہتے
Page 31
ہیں جو چرنے کے لئے جارہے ہوں.الْمَاءُ.جَرٰی اور جب سَربَ الْمَاءُ کا فقرہ استعمال کیا جائے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے پانی بہہ پڑا.فُلَانٌ فِی الْاَرْضِ.ذَھَبَ عَلٰی وَجْہِہٖ فِیْہَا وَمَضَی اور جب سَرَبَ فُلَانٌ فِی الْاَرْضِ کہا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ زمین میں چلا.(اقرب) تفسیر.آنحضرت ؐ کے مقابل کفار کے دو طریق کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں دو ہی طریق استعمال کیا کرتے تھے.کبھی پبلک میں دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہم اس اس طرح آپؐ کو تباہ کر دیں گے تا آپؐ ڈر جائیں اور کبھی مخفی طور پر مشوروں اور منصوبوں کے ذریعہ سے آپؐ کو ہلاک کرنے کی کوششیں کرتے تھے.کبھی آپؐ پر دن کو حملہ کرتے تھے.جیسا کہ اوجھری کے سرپر ڈال دینے(بخاری کتاب الوضوء باب اذا القی علی ظھر المصلی قذر اوجیفۃ..) یا آپؐ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کے واقعات میں اور کبھی رات کو حملہ کرتے تھے جیسا کہ ہجرت کی رات کو وہ حملہ آور ہوئے تھے.اور دنیا میں دشمن کو خوف زدہ کرنے کے یہی دو طریق ہوا کرتے ہیں.یعنی علی الاعلان دھمکیاں یا مخفی مشورے و منصوبے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی.پھر تمہارے ظاہری اور مخفی حملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ اس کی (یعنی اللہ کی) طرف سے اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی (ایک دوسرے کے) پیچھے آنے والی (ایک مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا ملائکہ کی )جماعت (حفاظت کے لئے) مقرر ہے جو اس کی اللہ کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں اللہ (تعالیٰ) کبھی بھی بِاَنْفُسِهِمْ١ؕ وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ١ۚ وَ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلے.اور جب اللہ( تعالیٰ) کسی قوم کے
Page 32
مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ۰۰۱۲ متعلق عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس( عذاب) کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس( یعنی اللہ) کے سوا ان کا اورکوئی (بھی )مددگار نہیں (ہو سکتا).حلّ لُغَات.مُعَقِّبَاتٌ.عَقَّبَ میں سے ہے اور عَقَّبَہٗ کے معنے ہیں جَاءَ بِعَقِبِہٖ.اس کے پیچھے پیچھے آیا.اَتٰی بِشَیْءٍ بَعْدَہُ.یا اس کے بعد کوئی کام کیا.عَقَّبَ فُلَانٌ کے معنے ہیں غَزَا عَلَی الْعَدُوِّ ثُمَّ ثَـنَّی مِنْ سَنَتِہٖ کہ دشمن پر ایک حملہ کرنے کے بعد پھر اسی سال دوسرا حملہ کیا.اور جب عَقَّبَ فِی الْاَمْرِ کہا جاوے تو اس کے معنے ہوتے ہیں تَرَدَّدَ فِیْ طَلَبِہٖ مُجِدًّا کسی بات کی تلاش میں بار بار کوشش کی.علاوہ ازیں عَقَّبَ کے کئی اور استعمال ہیں.مثلاً عَقَّبَ فِی الصَّلٰوۃِ.صَلَّی فَـمَکَثَ فِی مَوْضِعِہٖ یَنْتَظِرُ صَلٰوۃً اُخْرٰی.نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا رہا اَ لْحَاکِمُ عَلٰی حُکْمِ سَلَفِہٖ.حَکَمَ بَعْدَ حُکْمِہٖ بِغَیْرِہِ.حاکم نے اپنے سے پہلے کے فیصلہ کے بعد کوئی اور فیصلہ کردیا.اور اَلْمُعَقِّبَاتُ کے معنی ہیں مَلَائِکَۃُ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ.دن اور رات کے فرشتے.التَّسْبِیْحَاتُ یَخْلُفُ بَعْضُہَا بَعْضًا.تسبیحات.کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں.اللَّوَاتِیْ یَقُمْنَ عِنْدَ أَعْجَازِ الْاِبِلِ الْمُعْتَرِکَاتِ عَلَی الحَوْضِ فَاِذَا اِنْصَرَفَتْ نَاقَۃٌ دَخَلَتْ مَکَانَہَا اُخْرٰی وہ اونٹنیاں جو اونٹوں کے پانی پر ازدحام کے وقت پیچھے کھڑی رہتی ہیں اور جب ایک اونٹنی پانی پی کر چلی جاتی ہے تو دوسری اس کی جگہ آجاتی ہے.(اقرب) معقبات سے مراد اس جگہ معقبات سے مراد پہرہ دار اور توابع آگے پیچھے چلنے والے ہیں.لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ اَیْ مَلَائِکَۃٌ یَتَعَاقَبُوْنَ عَلَیْہِ حَافِظِیْنَ.مُعَقِّبَاتٌ سے مراد وہ فرشتوں کی جماعت ہے جو حفاظت کے لئے یکے بعد دیگرے آتے ہیں.(مفردات) ــــ؎ مَرَدٌّ رَدَّ کا مصدر ہے اور رَدَّعَنْ وَجْہِہٖ کے معنے ہیں صَرَفَہٗ اس کو پھیر دیا.عَلَیْہِ الشَّیْءَ.لَمْ یَقْبَلْہُ رَدَّ عَلَیْہِ الشَّیْءَ کے معنے ہیں.عطیہ کو قبول نہ کیا اور واپس کر دیا.اِلَی مَنْزِلِہٖ.اَرْجَعَہٗ اس کو واپس اس کے مکان ؎ پس لَہٗ مُعَقِّبَاتٌ کے معنے ہوئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے آگے پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت ہے.(۲) اس کے لئے دشمنوں کے حملوں کو روکنے والے اور اس کی تائید میں بار بار حملے کرنے والے مقرر ہیں.(۳) لَہٗ کی ضمیرکا مرجع مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ میں لفظ مَنْ ہو تو یہ مراد ہوگی کہ ہر انسان کی حفاظت کے لئے خدا نے پہرہ دار مقرر کر رکھے ہیں.
Page 33
کی طرف لوٹا دیا.پس مَرَدّ مصدر کے جو اسم فاعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ معنے ہوں گے ہٹانے والا، واپس کرنے والا.(اقرب) اور لَامَرَدَّ لَہٗ کے معنے ہوں گے اسے کوئی ہٹانے والا نہیں.وَالٍ.وَلِیَ سے اسم فاعل ہے اور وَلِیَ الشَّیْ ءَکے معنے ہیں مَلَکَ اَمْرَہٗ وَقَامَ بِہٖ.کسی بات کا مالک بنا اور اس کی ذمہ داری کو اٹھایا.فُلَانًا وَعَلَیْہِ.نَصَرَہٗ.اور وَلِیَ فُلَانًا کے معنے ہیں اس کی مدد کی.فُلَانًا وَلَایَۃً.اَحَبَّہٗ اور جب وَلَایَۃٌ مصدر ہو تو اس کے معنے ہوں گے محبت کی.(اقرب) پس وَالٍ کے معنے ہوں گے (۱) مددگار.(۲)نگران (۳)محافظ.تفسیر.لَہٗ مُعَقِّبَاتٌ کی ضمیر آنحضرت ؐ کے لئے ہے لہ کی ضمیر میرے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ذات کی طرف پھرتی ہے یعنی جیسے بادشاہوں کے گرد پہرہ دار ہوتے ہیں ویسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے مُعَقِّبَاتٌ ہیں.آنحضرت ؐ کی حفاظت کا ثبوت ان معنوں کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے.چنانچہ ابونعیم نے الدلائل میں اور طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں نقل کیا ہے کہ عامر ابن طفیل اور عربد ابن قیس دو شخص حضورؐ کے پاس آئے.عامر نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ولایت امر یعنی اپنے بعد خلافت مجھے دے دی جائے گی؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری اس شرط کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خلافت تمہیں اور تمہاری قوم کو کبھی نہ ملے گی.اس نے اس بات سے ناراض ہوکر کہا کہ پھر میں ایسے سوار لاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تمہیں اس کی توفیق ہی نہ دے گا.اس پر وہ دونوں ناراض ہوکر چلے گئے.راستہ میں عربد نے کہا آؤ پھر واپس چلیں.میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو باتوں میں لگاؤں گا تم پیچھے سے تلوار کے ذریعہ سےان کا کام تمام کر دینا.عامر نے کہا کہ اس طرح بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا.اور آپؐ کے ساتھی ہمیں قتل کر دیں گے اس نے جواب دیا کہ کوئی خطرہ کی بات نہیں.ہم دیت دے دیں گے.چنانچہ وہ دونوں واپس آئے.عربد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا اور عامر نے چاہا کہ آپ ؐ کو پیچھے سے تلوار مار دے مگر وہ تلوار سونت کر رہ گیا اور وار نہ کرسکا.حدیثوں میں تو آتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر فالج گرا.لیکن چونکہ انہی حدیثوں میں یہ ذکر بھی ہے کہ بعد میں وہ سوار ہوکر گیا اور ہاتھ کا استعمال کرتا رہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فالج نہیں گرا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر رعب طاری کر دیا اور اسے حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے اس کا ہاتھ کھڑا کا کھڑا رہ گیا.لکھا ہے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو اس نے ہاتھ تلوار کے قبضہ پر رکھا ہوا تھا.حضور اس کے
Page 34
ارادہ کو بھانپ گئے اور پیچھے ہٹ گئے.مگر ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کیا.اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے.عربد پر راستہ میں بجلی گری اور عامر کاربنکل سے ہلاک ہوگیا.صحابہؓ کہتے ہیں کہ ہم اس واقعہ پر لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ والی آیت چسپاں کیا کرتے تھے.(روح المعانی زیر آیت ھٰذا) صحابہ لَہٗ مُعَقّبَاتٌ والی آیت آنحضرت صلعم کے لئے خاص سمجھتے تھے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ اس آیت کو عام سمجھنے کی بجائے خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سمجھا کرتے تھے.آنحضرت ؐ کی حفاظت فرشتے کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام زمانہ نبوت اس حفاظت کا ثبوت دیتا ہے.چنانچہ مکہ معظمہ میں آپؐ کی حفاظت فرشتے ہی کرتے تھے ورنہ اس قدر دشمنوں میں گھرے ہوئے رہ کر آپؐ کی جان کس طرح محفوظ رہ سکتی تھی.ہاں مدینہ تشریف لانے پر دونوں قسم کی حفاظت آپ کو حاصل ہوئی.آسمانی فرشتوں کی بھی اور زمینی فرشتوں یعنی صحابہؓ کی بھی.بدر کی جنگ اس ظاہری اور باطنی حفاظت کی ایک نہایت عمدہ مثال ہے.حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپؐ نے اہل مدینہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر آپ مدینہ سے باہر جاکر لڑیں گے تو مدینہ والے آپؐ کا ساتھ دینے پر مجبور نہ ہوں گے.بدر کی لڑائی میں آپؐ نے انصار اور مہاجرین سے لڑنے کے بارہ میں مشورہ فرمایا.مہاجرین بار بار آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے پر زور دیتے تھے لیکن حضور ان کی بات سن کر پھر فرما دیتے کہ اے لوگو! مشورہ دو.جس پر ایک انصاری (سعد بن معاذ) نے کہا کیا حضور کی مراد ہم سے ہے.حضور نے فرمایا ہاں! اس نے کہا کہ بے شک ہم نے حضور سے معاہدہ کیا تھا کہ اگر باہر جاکر لڑنے کا موقع ہوگا تو ہم حضور کا ساتھ دینے پر مجبور نہ ہوں گے لیکن وہ وقت اور تھا.جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ آپؐ خدا کے ر سول برحق ہیں تو اب اس مشورہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے.ہم اصحاب موسیٰ ؑ کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جاکر لڑو.ہم یہاں بیٹھے ہیں.بلکہ ہم حضور کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے لڑیں گے اور دشمن آپ تک ہرگز نہ پہنچ سکے گا جب تک کہ وہ ہماری لاشوں کو روندتا ہوا نہ گزرے(بخاری کتاب المغازی باب قول اللہ تعالٰی اذ تستغیثون ربکم..).معقبات میں صحابہ بھی داخل ہیں یہ مخلصین بھی میرے نزدیک ان معقبات میں سے تھے جو خدا تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کے لئے مقرر فرما دیئے تھے.ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تیرہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں.مگر میرے دل میں بارہا یہ خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں بجائے ان لڑائیوں میں حصہ
Page 35
لینے کے اس فقرہ کا کہنے والا ہوتا جو سعد بن معاذ کے منہ سے نکلا.(بخاری کتاب المغازی).مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ.خدا کے حکم کے ماتحت حفاظت کرتے ہیں.یعنی قومیت یا ضد کے خیال سے نہیں کرتے اور نہ رشتہ داری یا حکومت کے خوف سے.بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے.دین کے سوا کوئی چیز ان کو جمع کرنے والی نہیں تھی.صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر کو یہ امر محسوس بھی ہوا اور اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ بھی دیا کہ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) ان لوگوں پر اعتماد نہ کرنا یہ بن بن کی لکڑیاں تیرے کس کام آئیں گی(سیرت النبی لابن ہشام زیر عنوان امر الحدیبیۃ) مگر باوجود کسی دنیوی واسطہ کی عدم موجودگی کے وہ لوگ سب سے زیادہ وفادار ثابت ہوئے.مُعَقِّب کے معنے روکنے والے کے بھی ہوتے ہیں معقب کے معنے روکنے والے کے بھی ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے آیت کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے لئے دشمنوں کے حملہ کو روکنے والے اور اس کی تائید میں بار بار حملہ کرنے والے مقرر ہیں.لہ کی ضمیر کا مرجع سواء منکم بھی ہو سکتا ہے لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہر انسان کی حفاظت کے لئے بھی خدا نے پہرہ د ار مقرر کر رکھے ہیں.اس صورت میں لہ کی ضمیر کا مرجع سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ ہوگا.اگر انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوجائے کہ ہر لحظہ اس کے اندر کس قدر زہر جارہا ہے.ایک دوسرے کے سانس کے زہریلے کیڑے اندر داخل ہورہے ہیں.مگر اللہ تعالیٰ نے ان تمام زہروں کے لئے ایسا قانون مقرر کردیا ہے کہ جو جسم میں داخل ہوتے ہی زہر کو تباہ کردیتا ہے.انسان کے لئے ہر آن ہزاروں خطرات ہیں.بیماریاں، عقل کے صدمات، اموال کے نقصان اور عزت کے صدمات وغیرہ طرح طرح کے خطرات ہر وقت پیش آتے رہتے ہیں.ان سب سے اللہ تعالیٰ ہی انسان کی حفاظت فرماتا ہے اور جب کسی پر موت یا کوئی اور صدمہ آنا ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت اٹھا لیتا ہے.اس مضمون سے کافروں کو ایک سبق اس مضمون سے کافروں کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم شرارتوں میں ہی بڑھتے رہو گے تو یاد رکھو !تمہارا آرام سب ہماری ہی حفاظت کے سبب سے ہے.اس صورت میں ہم اپنی حفاظت تم سے واپس لے لیں گے اور تم تباہ ہو جاؤ گے.اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ بروں کے ساتھ نیک
Page 36
سلوک نہیں کرتا بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نیکوں کے متعلق اپنے رویہ کو نہیں بدلتا.جب تک ان میں تبدیلی واقع نہ ہو جائے اور وہ برے نہ بن جائیں.یعنی برے کے ساتھ تو خدا کا سلوک نیک ہوسکتا ہے مگر نیک کے ساتھ برا نہیں ہوا کرتا.جب تک وہ خود بدل نہ جائے.یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے.پراگندہ کردینے والے ابتلاء آنا قوم کی حالت کے تغیر پر دال ہے جب کسی قوم کی حالت خراب ہورہی ہو اور اسے ایسے ابتلا پیش آویں جو اسے پراگندہ کر دیں اور تباہ کر دیں جیسا کہ تغیر کا حقیقی منشاء ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کی حالت بدل چکی ہے.مِنْ وَّالٍ کے معنے.وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ١ۚ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.سوء کے معنے بدی یا تکلیف کے ہوتے ہیں.فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دینے کا فیصلہ کرے تو پھر کوئی اس کو روکنے والا نہ ہوگا.وَلِیَ الْاَمْرَ کے معنے مَلَکَہٗ آتے ہیں.تو فرمایا کہ خدا کے مقابلہ میں کوئی ان کا نگران والی و محافظ نہ ہوگا.اس میں وحدت ملکیت کی طرف اشارہ کیا ہے.یعنی جب ایک ہی مالک ہے تو اس کی چھوڑی ہوئی چیز کو کون حفاظت میں لے سکتا ہے.پس اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر بے مدد ہی رہ جاؤ گے کیونکہ دوسرا کوئی آقا تو ہےنہیں.اس آیت میں صاف طور پر کفار کو بتلا دیا گیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حفاظت کروں گا مگر تم سے حفاظت کو چھین لوں گا.هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنْشِئُ وہی ہے جو تمہیں بجلی (کی چمک) دکھا تا ہے خوف کے لئے (بھی) اور طمع کے لئے (بھی) السَّحَابَ الثِّقَالَۚ۰۰۱۳ اوربھاری بادل اٹھاتا ہے.حلّ لُغَات.اَنْشَأَیُنْشِیُٔ أَنْشَأَ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اَنْشَأَہٗ اِنْشَاءً کے معنی ہیں رَبَّاہُ.اس کی پرورش کی.الشَّیْءَ اَحْدَثَہٗ اور اَنْشَأَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں کسی چیز کو بنایا.اَللہُ الشَّیْءَ.خَلَقَہٗ اللہ نے کسی کو پیدا کیا.ا ور أَنْشَأَ اللہُ الْخَلْقَ کے معنی ہیں اِبْتَدَأَ خَلْقَھُمْ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کی ابتداء کی.فُلَانٌ الْحَدِیْثَ.وَضَعَہٗ جب حدیث کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں کوئی بات بنائی.اللہُ السَّحَابَۃَ رَفَعَھَا اور أَنْشَأَ اللہُ السَّحَابَۃَ کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بلند کیا.فُلَانٌ دَارًا.
Page 37
بَدَأَ بِنَاءَھَا مکان کے بنانے کی ابتداء کی.زَیْدٌ أَنْشَدَ شِعْرًا اَوْ خَطَبَ بِخُطْبَۃٍ فَاَحْسَنَ فِیْھِمَا.زید نے اچھی طرح شعر کہے اور لیکچرار نے بلند پایہ تقریر کی.(اقرب) پس يُنْشِئُ السَّحَابَ کے معنے ہوں گے (۱)بادلوں کو بناتا ہے.بادلوں کو اٹھاتا ہے.السَّحَابَ.اَلْغَیْمُ کَانَ فِیْہِ مَاءٌ اَوْلَمْ یَکُنْ فِیْہِ.السَّحَاب.سَحَابَۃٌ کی جمع ہے اور اس کے معنے ہیں بادل.خواہ وہ برسنے والا ہو یا نہ ہو.اَلْوَاحِدَۃُ سَحَابَۃٌ.یہ اسم جنس ہے.مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے.اَلسَّحَابُ الْمُسَخَّرُ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ میں واحد ہے اور وَیُنْشِیُٔ السَّحَابَ الثِقَال میں جمع.ثِقَالٌ کا لفظ ثَقِیْلٌ (بھاری) کی جمع ہے جو خفیف (ہلکے) کی ضد ہے.(اقرب) تفسیر.بجلی کی چمک میں خوف اور فوائد.برق سے لوگوں کے لئے خوف اور طمع دونوں پیدا ہوتے ہیں.خوف اس لئے کہ بجلی گر کر ہلاک نہ کردے اور طمع اس لئے کہ عام طورپر بجلی زیادہ تبھی چمکتی ہے جب بادل زیادہ برسنے والا ہوتا ہے.اگرچہ ہمارے ملک میں بھی مشہور ہے کہ جو ’’گرجتے ہیں برستے نہیں‘‘ مگر وہ خاص قسم کی گرج ہوتی ہے.علاوہ ازیں بجلی کی چمک سے رحم مادر میں بچوں کو اور ایسا ہی بعض پودوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے.مگر ساتھ ہی اس کی چمک سے کئی بیماریو ںکے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں.وبائیں دور ہوجاتی ہیں.گویا بجلی کی چمک میں خوف بھی ہے اور فوائد بھی.یہی حال بھاری بادلوں کا ہوتا ہے.کبھی وہ رحمت بن کے دنیا کی آبادی کا باعث ہو جاتے ہیں اور کبھی وہی زحمت بن جاتے ہیں اور فصلوں کو برباد اور شہروں کو غرق کر دیتے ہیں.اس مثال سے بتایا ہے کہ ایک ہی چیز بعض کی تباہی کا اور بعض کی ترقی کا موجب بن جاتی ہے.بجلی چمکتی ہے، بادل آتے ہیں.ان سے کئی تباہ ہو جاتے ہیں اور کئی بے شمار فوائد حاصل کرتے ہیں.پس ظاہر ہے کہ اچھے یا برے نتائج صرف کسی چیز کے اچھے یا برے ہونے سے متعلق نہیں بلکہ اس تعلق سے متعلق ہیں.جو اس چیز کو کسی دوسری چیز سے جاکر پیدا ہوتا ہے.مثلاً کوئی پوچھے کہ بھاری بادل اچھے ہوتے ہیں یا کہ نہیں.تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاسکتا.تاوقتیکہ موقع و حالات کو نہ دیکھ لیا جائے.جب بارش آتی ہے تو جس کی عمارت بن رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر بارش آگئی تو میں تباہ ہو جاؤں گا مگر اسی وقت زمیندار جس کا کھیت خشک سالی کی و جہ سے تباہ ہورہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ اگر بارش نہ ہوئی تو میں برباد ہو جاؤں گا.پس فرمایا کہ چند دن کا فائدہ یا ضرر نسبتی امر ہے.پس کفار کو ظاہری سامانوں پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے.مال رشتہ دار اور حکومتیں ہر اک کے لئے اچھی ہی نہیں ہوتیں.یہ اگر ایک کو بچا لیتی ہیں تو دوسرے کو تباہ کر دیتی ہیں.
Page 38
قوموں کی ترقی اور تنزل کی ایک لطیف مثال اس لئے وہ ان سامانوں کو نہ دیکھیں جو ان کے پاس ہیں بلکہ اپنے دل کی حالت کو دیکھیں اگر دل خراب ہوچکے ہیں تو ظاہری سامان ترقی کا نہیں تنزل کا موجب ہوں گے.یہ ایک اتنا لطیف اور وسیع مضمون ہے کہ اس کے ذریعہ سے قوموں کے تنزل اور ترقی کے اسباب پر ضخیم مجلدات لکھی جاسکتی ہیں.وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ١ۚ وَ اور کڑک اس کی تعریف کے ساتھ (ساتھ) اس کی پاکیزگی کا اظہار بھی کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف کے يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَ هُمْ سبب سے( ایسا ہی کرتے ہیں) اور وہ گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے.پھر جن پر چاہتا ہے انہیں نازل کر تا ہے اور وہ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ١ۚ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِؕ۰۰۱۴ اللہ کے بارہ میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے.حلّ لُغَا ت.یُسَبِّحُ.سَبَّحَ ماضی سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے.اور سَبَّحَ اللّہَ کے معنے ہیں نَزَّھَہٗ کہ اللہ کی پاکیزگی کا اظہار کیا اور کبھی سَبَّحَ کے ساتھ ل کا صلہ لا کر بھی اس کو متعدّی بنایا جاتا ہے.(اقرب) اور یُسَبّحُ الرَّعْدُ کے معنے ہوں گے کہ کڑک اللہ کی پاکیزگی کا اظہار کرتی ہے.اَلرَّعْدُ.رَعَدَ کا مصدر ہے اور رَعَدَ السِّحَابُ کے معنے ہیں صَاتَ وَضَجَّ لِلْاِمْطَارِ.بادل برسنے کے لئے گرجا اَلرَّعْدُ کے معنے ہیں صَوْتُ السَّحَابِ بادل کی آواز، کڑک.(اقرب) اَلصَّوَاعِقُ.صَاعِقَۃٌ کی جمع ہے اور صَاعِقَہ کے معنی ہیں اَلْمَوْتُ.موت کُلُّ عَذَابٍ مُھْلِکٍ.ہر مہلک عذاب.صَیْحَۃُ الْعَذَابِ.عذاب کی آواز.نَارٌ تَسْقُطُ مِنَ السَّمَآءِ فِیْ رَعْدٍ شَدِیْدٍ لَا تَـمُرُّ عَلَی شَیْءٍ اِلَّا اَحْرَقَتْہُ.وہ آگ جو بادل سے کڑک کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور جس چیز پر گرے اسے جلادیتی ہے.(اقرب) اَلْمِحَالُ.مَاحَلَ کا مصدر ہے اور مَاحَلَہٗ کے معنی ہیں.مَاکَرَہٗ وَکَایَدہٗ.کسی کی تدبیر کے خلاف تدبیر کی.عَادَاہُ.بالمقابل دشمنی کا اظہار کیا.قَاوَاہُ.کسی کے بالمقابل قوت و غلبہ کااظہار کیا.اور اَلْمِحَالُ کے معنی ہیں.اَلْکَیْدُ.تدبیر.رَوْمُ الْاَمرِ بِالْحِیَلِ.حیلوں کے ذریعوں سے کسی کام کے کرنے کا قصد کرنا.اَلتَّدْبِیْرُ.
Page 39
تدبیر.اَلْمَکْرُ.تجویز.اَلْقُدْرَۃُ.طاقت.اَلْجِدَالُ.جھگڑا.اَلْعَذَابُ.عذاب.اَلْعِقَابُ.سزا.اَلْعَدَاوَۃُ.دشمنی.اَلْقُوَّۃُ وَالشِّدَّ ۃُ.طاقت و رعب.اَلْھَلَاکُ.ہلاک ہونا.اَلْاِھْلَاکُ.کسی کو ہلاک کرنا.(اقرب) بعض نے مِحَالٌ کو حَوْلٌ اور حِیْلَۃٌ سے مشتق قرار دیا ہے.(مفردات) پس هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ کے معانی ہوں گے کہ اللہ کی تدبیر بڑی سخت ہے.اس کی پوشیدہ تدبیریں کارگر ہوکر رہتی ہیں.اس کی قدرت بھاری ہے.جب وہ بندوں کے حقوق دلواتا ہے تو اس کی سزا سخت ہوتی ہے.جب اس کی طرف سے ہلاکت آتی ہے تو سخت ہوتی ہے.تفسیر.فرمایا تم مسلمانوں کو مصائب اور آفات کا شکار دیکھ کر خوش ہوتے ہو.کہ یہ بجلیاں انہیں تباہ کر دیں گی مگر تم اس میں دھوکا کھارہے ہو.نہ بجلی ہر حالت میں اور ہر شے کے لئے ہلاکت کا موجب ہوتی ہے اور نہ بادل ہر حالت میں اور ہر شئے کے لئے فائدہ کا موجب ہوتا ہے.مصائب مومن کے لئے تباہی کا موجب نہیں ہوتے بلکہ ترقی کا.وہ اس کی چھپی ہوئی طاقتوں کو ابھارنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں وہ اس کے حوصلوں کو بلند کردیتے ہیں.وہ اسے اپنے رب کے اور بھی قریب کردیتے ہیں.آخر کڑک اور بجلی بھی تو خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ اس کے مخلص بندوں کی تباہی کا موجب کس طرح ہوسکتی ہے؟ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرسکتی جس سے خدا کی ذات پر عیب لگتا ہو.وہ بھی خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے.اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر کر ان کو تباہ کر دے (نعوذباللہ) تو خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراض آتا ہے پس جس کے ساتھ خدا ہو وہ اس کا تو بھلا ہی کرے گی.اگر گرے گی تو وہ تم پر ہی گرے گی.فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح کررہے ہیں.یعنی رعد خود تو کوئی چیز نہیں.فرشتے بھی جو پہلا سبب ہیں اور سب اسباب ان کے اشارہ پر نتائج ظاہر کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہیں.جس کےساتھ خدا تعالیٰ ہوگا سب سامان اس کے فائدہ کے نتائج پیدا کر یں گے پس جس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہوگا دنیا کے سامان بھی خواہ کسی صورت میں ظاہر ہوں آخرکار اس کے فائدے کے نتائج پیدا کریں گے.وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ١ۚ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ.یعنی تم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ چمکنے والی بجلیاںکن پر گر سکتی ہیں.خدا جو ان کو گرانے والا ہے کیا ان پر گرائے گا جو اس کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں.یا ان پر جو اس کے متعلق جھگڑ رہے ہیں.اور اس کے دین کی مخالفت میں کھڑے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ انہی پر گرائے گا جو اس کے مخالف ہیں.وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ کہہ کر اس بات کو صاف طور سے بتا دیا کہ یہ عام قانون قدرت کا ذکر نہیں ہورہا بلکہ دشمنانِ اسلام اور خدا تعالیٰ کے بارہ میں جھگڑنے والوں کے لئے ایک سخت عذاب کی پیشگوئی ہے.شدید المحال کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا آسان نہیں کیونکہ اس کی
Page 40
تدابیر باریک در باریک اور مضبوط ہوا کرتی ہیں اور پھر ان کے نتائج بھی بہت سخت نکلا کرتے ہیں.لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ١ؕ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا نہ ٹلنے والا بلاوا اسی کا ہے اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان( کی دعا) کا کوئی جواب نہیں دیتے (ہاں) مگر يَسْتَجِيْبُوْنَ۠ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ اس (شخص) کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلارہا ہو لیکن وہ (یعنی پانی) اس تک کبھی نہ پہنچے گا اور لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ١ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ۰۰۱۵ کافروں کی (چیخ و) پکارضائع ہی جائے گی.حلّ لُغَات.دَعْوَۃٌ.دَعَا کا مصدر ہے اور دَعَا فُلَانًا دَعْوَۃً کے معنے ہیں طَلَبَہٗ لِیَأْکُلَ عِنْدَہٗ.کہ اسے کھانے پر بلایا.پس دَعْوَۃٌ کے معنے ہوں گے ’’بلاوا‘‘.(اقرب) اَلحَقَّ.اَلْحَقُّ.حقَّ کا مصدر ہے.اور حَقَّہٗ حَقًّا کے معنے ہیں غَلَبَہٗ عَلَی الْحَقِّ.حق کی وجہ سے اس پر غالب آیا.وَالْاَمْرَ: اَثْبَتَہٗ وَاَوْجَبَہٗ.کسی امر کو ثابت کیا اور واجب کیا.کَانَ عَلٰی یَقِیْنٍ مِنْہٗ.کسی معاملہ پر یقین سے قائم تھا.الخَبَرَ.وَقَفَ عَلَی حَقِیْقَتِہِ اور حَقَّ الْخَبَرَ کے معنے ہوں گے اس کی حقیقت سے آگاہ ہوا اور اَلْحَقُّ کے معنے ہیں ضِدُّ الْبَاطِلِ سچ.الأَمْرُ الْمَقْضِیُّ فیصلہ شدہ بات.اَلْعَدْلُ.عدل.اَلْمِلْکُ.ملکیت.اَلْمَوْجُودُ الثَّابِتُ.موجود و قائم.اَلْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ.یقین.اَلْمَوْتُ.موت اَلْحَزْمُ دانائی.(اقرب) پس لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ کے معنے ہوں گے (۱)سچائی کی تائید میں اٹھنے والی آواز صرف خدا ہی کی ہوتی ہے.(۲) خدا تعالیٰ ہی کی آواز ضرور غالب ہوکر رہتی ہے.(۳)جو پکارنا فائدہ مند ہوسکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حضور پکارنا ہے.(۴)وہی پکارے جانے کا مستحق ہے.(۵)تقدیر کا ٹلانا اسی کا کام ہے.یَسْتَجِیْبُوْنَ.اِسْتَجَابَ سے ہے اور اِسْتَجَابَ کے معنے ہیں رَدّلَہُ الْجَوَابَ.اس کو جواب دیا.اور لَایَسْتَجِیْبُوْنَ کے معنے ہوئے وہ جواب نہیں دیتے.(اقرب) ضَلَالٌ ضَلَالٌ ضَلَّ کا مصدر ہے اور ضَلَّ عَنِّیْ کَذَا کے معنے ہیں ضَاعَ.ضائع ہو گیا.فُلَانٌ الْفَرَسَ
Page 41
وَالْبَعِیْرَ.ذَھَبَا عَنْہُ.اونٹ اور گھوڑا اس سے ضائع ہو گئے.(اقرب) اور ضَلَالٌ کے معنے ہوئے ضَیَاعٌ.ضائع ہونا.(لسان) اور مَادُعَاءُ الْکٰفِرِیْنَ اِلَّا فِیْ ضَلَالٍ کے معنے ہوئے کہ کافروں کی چیخ و پکار ضائع ہی جائے گی.تفسیر.لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ کے چار معنے جیسا کہ حل لغات میں لکھا گیا ہے اس آیت کے کئی معنی ہیں.(۱)سچائی کی تائید میں اٹھنے والی آواز صرف خداہی کی ہوتی ہے.یعنی عمدہ تعلیم جو سراسر حق ہو.جو غلطی سے پاک ہو.وہ صرف خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آسکتی ہے.انسان کی بنائی ہوئی تعلیم میں غلطیاں اور جھوٹ ہوتے ہیں.اس لئے یہ مت سمجھو کہ تمہاری تعلیمات اس کے مقابلہ میں ٹھہر سکیں گے.اس پاک تعلیم کا مقابلہ جب تمہاری غلطیو ںسے پر تعلیم کے ساتھ ہوگا تو دنیا کو خودبخود اس کی برتری کا یقین ہوجائے گا.اللہ ہی کی آواز پوری ہوکر رہتی ہے (۲) خدا تعالیٰ ہی کی آواز ہے جو ضرور غالب ہوکر رہتی ہے.دنیا کے بادشاہوں کی آوازیں بھی دب جایا کرتی ہیں.بادشاہ ایک مجرم کی سزا کا اعلان کرتا ہے مگر وہ ملک سے بھاگ جاتا ہے یا کسی کی ذلت کا سامان کرتا ہے مگر خود مر جاتا ہے.صرف ایک اللہ کی آواز ہے جو پوری ہوکر رہتی ہے اور کوئی اس میں روک نہیں ڈال سکتا.(۳) پکارنے کا فاعل بندہ کو قرار دیا جائے تو یہ معنے ہوتے ہیں کہ جو پکارنا حق کا موجب ہوسکتا ہے یعنی فائدہ اور کامیابی والا ہوسکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا ہے.یعنی اسی سے عجز کے ساتھ دعائیں مانگنا ہی کامیابی کی کلید ہے.(۴) وہی مستحق ہے سب عبادات کا جو اس کے سوا دوسرے کو پکارتا ہے وہ کسی کا حق کسی کو دیتا ہے اور اس طرح ظالم اور ناشکرگزار بنتا ہے.وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ۠ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ مَا هُوَ بِبَالِغِهٖ١ؕ وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ.بِشَیْءٍ سے بتلایا کہ جھوٹے معبودوں کی طرف سے انہیں ذرہ بھر بھی نفع نہیں پہنچتا.اگر کوئی دعا پوری ہو جاتی ہے تو وہ اتفاق کا نتیجہ ہوتا ہے.ان معبودان باطلہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا.اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ.یعنی ان کی پکار اپنے دونوں ہاتھ پھیلانے والے کی طرح ہوتی ہے.ادنیٰ چیز کو اعلیٰ مقام دینے والا اور اعلیٰ کو ادنیٰ دینے والا فوائد سے محروم رہ جاتا ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح اعلیٰ چیز کو ادنیٰ مقام دینے والا انسان فوائد سے محروم رہ جاتا ہے اسی طرح ادنیٰ کو اعلیٰ مقام دینے والا بھی اس کے فوائد سے محروم رہ جاتا ہے.کھرے سکہ کو کھوٹا سمجھنے والا بھوکا مرے گا.کیونکہ سکے کو استعمال نہ کرے گا.مگر کھوٹے کو کھرا سمجھنے والا بھی وقت پر تکلیف اٹھائے گا کیونکہ وہ اس کے کام نہ آئے گا.جو خدا تعالیٰ کی
Page 42
صفات سے آگاہ نہیں وہ اس کی رحمتوں سے محروم رہے گا.لیکن جو مخلوقات کو خدا بنائے گا وہ بھی ان مخلوقات کے فائدہ سے محروم رہے گا.مثلاً پانی انسان کے فائدہ کی ایک چیز ہے اور انسان کے کام آنے کے لئے بنایا گیا ہے.اگر کوئی پانی کو انسان کا ہی مقام دے دے اور جس طرح آدمی آدمی کو بلاتاہے ہاتھ پھیلا کر اسے بلانا شروع کردے تو پانی اس کےپاس نہ آئے گا.اور وہ پانی کے فوائد سے محروم رہ جائے گا.اسی طرح جو لوگ مخلوقات کو خدا بناتے ہیں وہ ان فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں جو ان مخلوقات میں مخفی ہیں.ستاروں اور دریاؤں کو خدا بنانے والے کب ان پر حکومت کرنے کی جرأت کرسکتے ہیں اور انسانوں کو خدا بنانے والے کب ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.ایک نبی کو خدا بنانے والا نبی والا فائدہ اٹھاتا نہیں اور خداوالا فائدہ نبی پہنچا نہیں سکتا.پس اس کے اصل فائدہ سے یہ شخص محروم رہ جاتا ہے.ہندوستان کے ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جانے کی بڑی وجہ ہندوستان کے ترقی کے میدان میں سب سے پیچھے رہ جانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پانی اور آگ کو خدا بنالیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے.جو ترقیات کے لئے دو بڑے رکن تھے.مگر یوروپین لوگوں نے ان سے کام لیاا ور ترقی کرکے آگے نکل گئے.ہندوؤں کی تو یہاں تک حالت ہے کہ جب دریائے گنگا سے انگریز نہر نکالنے لگے تو انہوں نےشور مچا دیا کہ ہمارے خدا کو کاٹنے لگے.مسلمان بھی اپنے تنزل کے وقت بزرگوں کو خدائی صفات دے کر ان سے دعائیں مانگنے لگے.نتیجہ یہ ہوا کہ عمدہ نمونہ کے طور پر کام آنا جو ان بزرگوں کا اصل فائدہ تھا اس سے محروم ہو گئے.اور دعائیں سننے کی ان وفات یافتہ بزرگوں میں طاقت ہی نہ تھی پس انہیں اعلیٰ مقام دے کر ان کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا.آپ فوائد سے محروم رہ گئے.اس آیت میں بتایا ہے کہ شرک انسانی ترقی میں ایک زبردست روک ہے.اور شرک کی وجہ سے انسان مخلوقات سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرسکتا جو خدا تعالیٰ نے ان میں پوشیدہ رکھا ہے.اَلضَّلَالُ کے معنے وَ مَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ.ان کی دعا ضائع اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے موقع پر نہیں پہنچتی.دعا تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس جائے.اگر خط یا پیغامبر کسی دوسری جگہ چلا جائے تو اس کا جانا نہ جانا برابر ہوتا ہے.اسی طرح فرمایا کہ کافروں کی دعا بے پتہ رہ جاتی ہے.دعا کی قبولیت کا اصل مقام تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.یہ لوگ اپنی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کا پتہ لکھتے تو ان کی دعائیں خدا تک ضرور پہنچتیں.اور ان کو جواب آجاتا.مگر ان لوگوں نے تو مخلوقات کا پتہ لکھنا شروع کر دیا.جو دعا کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے.اس لئے ان کی دعا ضائع ہوجاتی ہے اور تدبیریں ناکام رہتی ہیں.تقدیر کا ٹلانا خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ میں یہ بھی بتایا ہے کہ تقدیر کا ٹلانا خدا کے قبضہ میں
Page 43
ہے.پس جو اس سے تعلق نہیں رکھتا تقدیر اس کی مؤید نہیں ہوتی.اور وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ میں فرمایا کہ ان کی تدبیریں بھی ناقص غلط اور بے محل ہیں.گویا نہ تقدیر ان کے ساتھ رہی اور نہ تدبیر.تو اب ان کی کامیابی کی کون سی صورت باقی رہ گئی.وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اور جو( ذوی الارواح) آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں اور ان کے سائے بھی خوش ہو کر( کریں) یا ناخوش ہو کر ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِؑ۰۰۱۶ (ہر) صبح؎ اورشام؎ سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں.حلّ لُغَات.یَسْجُدُ.سَجَدَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور فُلَانٌ سَاجِدُ الْمَنْخِرِ کے معنے ہیں ذَلِیْلٌ خَاضِعٌ کہ وہ عاجز ذلیل ہے.اَلْبَعِیْرُ: خَفَضَ رَاْسَہٗ.اور سَجَدَ الْبَعِیْرُ کے معنے ہیں اونٹ نے اپنا سر نیچے گرایا.السَّفِیْنَۃُ لِلرِّیَاحِ.طَاعَتْہَا وَمَالَتْ بِمَیْلِہَا.کشتی کو جدھر ہوا نے چلایا وہ چل پڑی.(اقرب) لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کے معنے ہوں گے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے اور اس کے آگے عاجزی کرتی ہے.ظِلٰلُھُمْ.ظِلَالٌ ظِلٌّ کی جمع ہے.اقرب الموارد میں ہے اَلظِّلُّ نَقِیْضُ الضِحِّ وَھُوَ الْفَیْءُ.دھوپ کے مقابل کی چیز یعنی سایہ.جہاں سورج کی روشنی براہ راست نہ پہنچتی ہو.روشی کا نور اثر ڈال رہا ہو.اَوْھُوَ بِالغَدَاۃِ.وَالْفَیْءُ بِالْعَشِیِّ.بعض کہتے ہیں کہ ظل صبح کے سایہ کو کہتے ہیں جو دوپہر تک رہتا ہے اور فَیْءٌ دوپہر کے بعد سے لے کر شام تک کے سایہ کو کہتے ہیں.ظلال کے محاورہ کا استعمال قرآن مجید اور لغت میں (لیکن یہ قرآن کریم کے محاورہ کے خلاف ہے.کیونکہ اس جگہ آیا ہے کہ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ.یعنی صبح اور شام دونوں کے سایوں کو ظِلَال کہا ہے) وقال رُؤْبَۃُ کُلُّ مَوْضِعٍ تَکُوْنُ فِیْہِ الشَّمْسُ فَتَزُوْلُ عَنْہُ فَھُوَ ظِلٌّ.اور رؤبہ کے نزدیک ظلّ کے یہ معنی ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں سورج ہو.اور پھر وہاں سے ہٹ جائے.یُقَالُ ظِلُّ الْجَنّۃِ وَلَایُقَالُ فَیْؤُھَا ظِلَّ الْجَنَّۃِ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے متعلق فَیْءٌ کا لفظ نہیں استعمال کیا جاسکتا.اِنَّمَا ھِیَ دَائِمًا ظِلٌّ.کیونکہ وہ ہمیشہ ظل ہی رہتا ہے.نیز
Page 44
ظِلّ کے معنے ہیں مَایُرٰی مِنَ الْجِنِّ وَغَیْرِہٖ.بھوت وغیرہ.اَلْعِزُّ.عزت.اَلْمَنَعَۃُ.غلبہ اَلرَّفَاھَۃُ.خوشحالی.اَللَّیْلُ اَوْجُنْحُہٗ اَوْ سَوَادُہٗ.رات یا رات کا حصہ یا اس کی سیاہی مِنْ کُلِّ شَیْءٍ شَخْصُہٗ اَوْ کِنُّہٗ.ہر حیوان کا جسم یا ہر چیز کا وہ حصہ جو اس کے مغز کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بیرونی اثرات سے حفاظت میں رکھتا ہے.مِنَ الشَّبَابِ اَوَّلُہٗ جوانی کا ابتداء وَفِی الْاَسَاسِ وَکَانَ ذَالِکَ فِیْ ظِلِّ الشِّتَاءِ اَیْ فِیْ اَوَّلِ مَاجَاءَ.اور اساس میں ظِلّ کے لفظ کے ماتحت لکھا ہے کہ ظِلُّ الشِّتَاءِ کے معنے ہیں موسم سرما کا ابتدا.وَمِنَ الْقَیْظِ شِدَّتُہٗ.گرمی کے لئے آئے تو اس کے معنی ہیں.اس کی شدت.تَقُوْلُ سِرْتُ فِیْ ظِلِّ الْقَیْظِ.اَیْ فِیْ شِدَّتِہٖ.یَعْنِی سِرتُ فِیْ ظِلّ الْقَیْظِ کے معنے ہوں گے میں تیز گرمی میں چلا.وَمِنَ السَّحَابِ مَاوَارَی الشَّمْسَ مِنْہُ اَوْسَوَادُہٗ.بادل کا وہ حصہ جو سورج کو ڈھانپ لیتا ہے.یا اس کا سایہ.مِنَ النَّہَارِ لَوْنُہٗ اِذَا غَلَبَتْہُ الشَّمْسُ.چمکتی ہوئی دھوپ (اقرب) ھُوَ فِی ظِلِّہٖ.أَیْ کَنَفِہٖ.اور ھُوَ فِیْ ظِلِّہٖ کے معنے ہیں وہ اس کی حفاظت میں ہے.اس کے علاوہ ظِلَالُ.ظُلَّۃٌ کی بھی جمع ہے جس کے معنی ہیں اَلْغَاشِیَۃُ.ڈھانپنے والی چیز.سائبان.وَالْبُرْطُلَّۃُ اَیْ اَلْمِظَلّۃُ الضَّیِّقَۃُ.چھوٹا سائبان چھتری.وَفِیْ الْتَعْرِیْفَاتِ اَلظُّلَّۃُ ھِیَ الَّتِیْ اَحَدُ طَرَفَیْ جِذْعِہَا عَلَی حَائِطِ ھٰذِہِ الدَّارِ وَطَرَفُہَا الْاٰخَرُ عَلٰی حَائِطِ الْجَارِ الْمُقَابِلِ اور تعریفات میں ہے کہ ظُلَّۃٌ اس چھپر کو کہتے ہیں کہ جس کو راستہ پر سایہ کے لئے ڈالا جاتا ہے اور اس کا ایک کنارہ ایک گھر کی ایک دیوار پر ہو اور دووسرا کنارہ سامنے کی دیوار پر ہو.اَوَّلُ سَحَابَۃٍ تُظِلُّ.موسم کا سب سے پہلا سایہ کرنے و الا بادل.مَااَظَلَّکَ مِنْ شَجَرٍ.جو درخت سایہ دے.شَیْءٌ کَالصُّفَّۃِ یُسْتَتَرُ بِہِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ.ایسا چھپر جو سردی اور گرمی سے بچاؤ کے لئے بنایا گیاہو.(اقرب) اور مجمع البحار میں ہے اَلظِّلُّ.اَلْفَیْءُ الْحَاصِلُ مِنَ الْحَاجِزِ بَیْنَکَ وَبَیْنَ الشَّمْسِ مُطْلَقًا سورج اور انسان کے درمیان کسی روک کے آنے کی وجہ سے جو سایہ ہوتا ہے ظل کہلاتا ہے.وَمِنْہُ سَبْعَۃٌ فِیْ ظِلِّ الْعَرْشِ اَیْ فِیْ ظِلِّ رَحْمَتِہٖ.اور حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سات شخص عرش کے سایہ تلے ہوں گے یعنی اس کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے.وَجَاءَ سَبْعَۃٌ فِیْ ظِلِّہٖ اَیْ فِیْ ظِلِّ اللہِ اور بعض حدیثوں میں سَبْعَۃٌ فِیْ ظِلِّہٖ آیا ہے کہ وہ اللہ کے سایہ میں ہوں گے.کہتے ہیں ھُوَ فِی عَیْشٍ ظَلِیْلٍ وَالْمُرَادُ ظِلُّ الْکَرَامَۃِ وہ خوب مزے کی زندگی بسر کررہا ہے.وَقَدْ یُکْنٰی مِنَ الْکَنَفِ.اور کبھی اس سے مراد حفاظت بھی لی جاتی ہے.وَفِی الْحَدِیْثِ اَلْکَافِرُ یَسْجُدُ لِغَیْرِاللہِ وَظِلُّہٗ یَسْجُدُلِلہِ اَیْ جِسْمُہٗ.یعنی حدیث میں ہے کہ کافر غیراللہ کے لئے سجدہ کرتا ہے اور اس کا سایہ یعنی جسم خدا تعالیٰ کے لئے.(مجمع البحار) اور مفردات راغب میں ہے اَلظِّلُّ ضِدُّ الضِّحِّ.ظِلّ
Page 46
اطاعت طوعاً ہے اور دوسرے حصہ کی کرھاً.مقصد یہ کہ گو بظاہر انسان آزاد نظر آتا ہے لیکن غور سے دیکھنے پر اس کے ہر فعل میں ایک جبر بھی نظر آتا ہے جو کسی بالا ہستی کے دخل پر دلالت کرتا ہے.دوسرے اس آیت میں تصرفات الٰہیہ کا طریق بتلایا ہے کہ بعض تصرفات اللہ تعالیٰ رسول کریم صلعم کی مدد کے لئے ایسے کرے گا کہ کفار اس میں اپنے آپ کو مجبور سمجھیں گے اور دل میں کڑھیں گے اور بعض تصرفات ایسے کرے گا کہ کفار خیال کریں گے کہ ہم ا ن کاموں میں اپنا فائدہ کررہے ہیں.حالانکہ ان کا جو نتیجہ پیدا ہوگا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیدا ہوگا.طوعاً کی مثال صلح حدیبیہ ہے کہ اس کی شرائط کفار نے زور سے منوائیں اور یہ سمجھ کر منوائیں کہ ان میں ہمارا فائدہ ہے مگر دراصل ان میں تھا مسلمانوں کا فائدہ.جیسا کہ بعد میں ظاہر ہوا.یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے اخراج کہ پہلے انہوں نے سمجھا اس طرح ہم نے مسلمانوں کو اپنے مرکز سے نکال دیا.لیکن ا س سے اسلام کی آزادی اور ترقی کی بنیاد رکھی گئی.کرہاً کی مثال فتح مکہ ہے کہ مجبوراً آنحضرت صلعم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے.دوسری مثال اس کی ایسے صحابہ سے حسن سلوک تھا جن کے خاندانوں اور قبائل سے وہ ڈرتے تھے.طوعاً وکرہاً کا مطلب پھر طوعاً و کرہاً کا فرق نیک و بد جماعت کے لحاظ سے بھی ہوسکتا ہے.یعنی مومن خدا کی اطاعت طوعاً کرتے ہیں اور کافر کرہاً.ظل کے مختلف معانی وَ ظِلٰلُهُمْ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے ظِلَالٌ.ظِلُّ کی بھی جمع ہے اور ظُلَّۃٌ کی بھی.ظِلّ کے ایک معنے سایہ کے ہیں.سایہ چونکہ عدم نور کے معنی رکھتا ہے.اس جگہ وہ مراد نہیں ہوسکتا.کیونکہ غیرموجود چیز کے لئے سجدہ کا لفظ نہیں آسکتا.ظِلّ کے دوسرے معنے کسی چیز کے وجود اور شخص کے بھی ہوتے ہیں.(۱)تمام اشیاء کے وجود قانون الٰہی کے ماتحت ہیں ان معنوں کے رو سے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ دلی اور قلبی سجدہ کے علاوہ تمام ا شیاء کے وجود قانونِ الٰہی کے ماتحت ہیں.حتیٰ کہ کافر کا جسم بھی خدا تعالیٰ کے قانون کے ماتحت ہوتا ہے اور اس طرح گو اس کا ذہن اور ایمان خدا تعالیٰ کا منکر ہوتا ہے مگر اس کا جسم خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگا ہوا ہوتا ہے.مجازاً ظل توابع کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں.سُلْطَانٌ ظِلُّ اللہِ بادشاہ اللہ کا سایہ ہے.یعنی اس کے ماتحت.(۲ ) تمام ذَوِی الاَرواح اور ان کے تابع وجود اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں پس اس کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ تمام ذی روح اور ان کے تابع وجود اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں.ظُلَّۃٌ جو اس لفظ کا دوسرا مفرد ہے اس کے معنی سایہ کرنے والے کے ہیں.جیسے سائبان وغیرہ.یا مجازاً سردار
Page 47
اور حکمران.اور معنے یہ ہوں گے کہ ان کے بڑے یا ان کو آرام پہنچانے والے وجود بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں.(۳) تمام موجودات اور ان کے تابع اور حکمران اللہ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں بہترین معنے یہ ہیں کہ دونو معنے اس جگہ مراد ہیں.ظِلٌّ والے بھی اور ظُلَّۃٌ والے بھی اور معنے یہ ہیں کہ تمام موجودات اور ان کے تابع اور ان کے حکمران سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں.پس ان لوگوں کو ہوشیار ہوجانا چاہیے کہ اگر محمد رسول اللہ صلعم کی مخالفت انہوں نے ترک نہ کی تو جوان سے اوپر کے وجود اور طاقتیں ہیں وہ بھی ان کی مخالف ہو جائیں گی اور جو ان کے تابع ہیں وہ بھی ان کے مخالف ہو جائیں گے.ان معنوں کی تصدیق اسی سورۃ کی ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے.فرماتا ہےاَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا (الرعد:۴۲) یعنے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کی حکومت کو دونوں طرف سے کم کرتے چلے آتے ہیں.یعنے بڑے خاندانوں میں سے بھی اور مزدور لوگوں میں سے بھی اور روز بروز کچھ لوگ مل کر محمد رسول اللہ صلعم کے ساتھ ملتے جاتے ہیں.آخر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ آئمۃ الکفر اکیلے رہ جائیں گے اور سب کا سب ملک محمد رسول اللہ صلعم کے ساتھ ہو جائے گا.بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ.یہ اس لئے فرمایا کہ ایک تو ان وقتوں میں سایہ لمبا ہوتا ہے اور دوسرے سایہ کا کامل ظہور سورج کے ادھر ادھر ہونے سے ہی ہوتا ہے.اسی طرح تابع کی طاقت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب آقا پاس نہیں ہوتا اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جبکہ حکومت وسیع پھیلی ہوئی ہو.پس بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ کہہ کر بتایا کہ خواہ تمہاری حکومت کتنی بھی وسیع کیوں نہ ہو تب بھی خدا تعالیٰ کے ماتحت ہو.اور ایسا ہی یہ بتایا کہ خواہ تم خود محمد رسول اللہ کے مقابلہ پر آؤ یا جب تم اپنے نوکروں یا غلاموں کو بھیجو دونوں صورتوں میں ہم تمہاری تدبیروں کو توڑ ڈالیں گے.یعنی نہ تم کچھ کرسکتے ہو اور نہ تمہارے سامان و تدابیر.لطیفہ.اس جگہ ظل کا ذکر کیا ہے اور جیسا کہ میں نے لغت کی رو سے ذکر کیا ہے ظل کے لئے اصل کا موجود ہونا ضروری ہے.اگر سورج نہ ہو تو کوئی ظل ہی نہیں.ظِلّی نبوت خاتم النبیین کی نبوت کو توڑ نہیں دیتی پس یہ کہنا کہ ِظلّیْ نبوت خاتم النبیین کی نبوت کو توڑ دیتی ہے بالکل غلط ہے.ظلی نبوت تو اصل کے وجود کو ثابت اور روشن کرتی ہے نہ کہ منسوخ.وہ اس کے لئے ایک زبردست شہادت ہے نہ کہ اس کے منافی.
Page 50
معبودوں کے متعلق ایسے دعاوی بھی پیش کرتے ہیں.افسوس مسلمانوں نے بھی اس زمانہ میں ایسی بات کہنی شروع کردی ہے اور حضرت مسیح کو پرندوں کا خالق قرار دے دیا ہے اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب پتہ نہیں لگ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پرندے کون سے ہیں اور حضرت مسیح کے بنائے ہوئے کون سے؟ حضرت مسیح موعود ؑ کا ایک مولوی سے حضرت مسیح ؑ کے پرندے پیدا کرنے کے متعلق سوال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک مولوی سے پوچھا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت مسیح ؑ ناصری پرندے پیدا کیا کرتے تھے آخر انہوں نے کیا چیز پیدا کی تھی.تو اس نے جواب دیا کہ چمگادڑ.جب میں نے اس سے پوچھا کہ مسیح کی چمگادڑیں کون سی ہیں اور خدا کی بنائی ہوئی چمگادڑیںکون سی ہیں تو ان مولوی صاحب نے فرمایا اب پتہ نہیں چلتا اور پنجابی میں کہا کہ ’’او ہن رل مل گیاں نے‘‘ یعنی اب تو وہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چمگادڑوں سے مل جل گئی ہیں(تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۲۰۶).افسوس کہ جس بات کی جرأت مکہ کے مشرکوں کو نہ ہوئی وہ کام مسلمانوں نے کس دلیری سے کیا.اور نہ سوچا کہ اس بے دلیل دعویٰ کو کون تسلیم کرے گا؟ واحد اور احد میں فرق اَلْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے لئے دو نام آتے ہیں.ایک واحد.دوسرا احد.احد نام تنزیہی ہے اور اس کے معنے ہیں اکیلا.اس کے ذکر پر دو یا تین کا خیال تک بھی ذہن میں نہیں آتا.یہ فردیت پر دلالت کرتا ہے اور کسی دوسرے یا تیسرے وجود کا خیال ذہن میں نہیں آتا.لیکن واحد کا لفظ جس کے معنے پہلے کے ہیں یہ نام ابتدائی نقط پر دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ دوسرے تیسرے کے وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ منبع ہے ساری مخلوق کا.باوجودیکہ کوئی مخلوق کمالات میں اس کی مشابہ نہیں.اور اس کی ذات تمام دنیا سے مستغنی ہے پھر بھی ہر چیز اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے.جس طرح دوسرے اور تیسرے کا وجود لازمی طور پر پہلے کی طرف رہنمائی کرتا ہے.خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ کی دلیل کے طورپر صفت واحد کو پیش کیا ہے یعنی اگر تم اس کوخالق نہ مانو گے تو وہ واحد نہیں رہتا.پھر تو بعض اشیاء اس پر دلالت کرنے کی بجائے کسی اور منبع کی طرف اشارہ کریں گی.پس اگر کوئی دوسرا خالق مانو گے تو اس کی وحدانیت سے انکار کرنا پڑے گا اور اگر اسے واحد نہ مانو گے تو اس امر کا اظہار کرنا پڑے گا کہ اس کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے.اَلْقَہَّارُ میں یہ بتایا ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز پیدا ہوکر پھر پیدا کرنے والے کے قبضہ سے نکل جائے اور اس کے لئے قبضہ میں رکھنے کے لئے کسی اور مددگار کی ضرورت ہو مگر اس جگہ یہ بات بھی نہیں.ہر چیز اللہ تعالیٰ کے
Page 51
قبضہ میں ہے اور اسی کی محتاج ہے.پس سب معبودانِ باطلہ بھی اس کے ماتحت ہیں.اور کوئی بھی ان میں سے خالق نہیں اور ان کی عبادت کرنا فضول ، عبث اور بے دلیل ہے.اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر (اس سے) کئی وادیاں اپنی (اپنی) مقدار کے مطابق بہ نکلیں السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا١ؕ وَ مِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اوراس سیلاب نےاوپر آجانی والی جھاگ کو اٹھا لیا اور جس( دھات) کو وہ کسی زیور یا کسی (اور) سامان کی طلب ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ١ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ میں آگ میں تپاتے ہیں اس میں( بھی) اس جیسا ایک جھاگ (ہوتا)ہے اسی طرح اللہ اللّٰهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ١ؕ۬ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً١ۚ وَ حق اور باطل (کے فرق) کو بیان کرتا ہے پھر جھاگ تو پھینکا جا کر تباہ ہو جاتا ہے اور اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ١ؕ كَذٰلِكَ جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے.يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَؕ۰۰۱۸ اللہ (تعالیٰ) تمام باتوں کو اسی طرح( کھول کر) بیان کرتا ہے.حلّ لُغَات.اَوْدِیَۃٌ وَادٍ کی جمع ہے اور وَادِی وَدَی سے مشتق ہے.وَدَی الشَّیْءُ وَدْیًا کے معنے ہیں سَالَ.بہہ پڑی.اور اَلْوَادِیْ اس سے اسم فاعل ہے یعنی بہنے والی.نیز اَلْوَادِی کے معنے ہیں مُنْفَرَجٌ بَیْنَ جِبَالٍ اَوْ تِلَالٍ اَوْآکَامٍ یَکُوْنُ مَنْفَذًا لِلسَّیْلِ.کہ وادی پہاڑوں یا ٹیلوں کی درمیانی جگہ کو کہتے ہیں.جس میں سیلاب کا پانی بہتا ہے.وَفِیْ مُفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ ’’اَلْوَادِیْ اَلْمَوْضِعُ الَّذِیْ یَسِیْلُ فِیْہِ الْمَآءُ وَمِنہُ سُمِّیَ
Page 52
الْمَفْرَجُ بَیْنَ الجَبَلَیْنِ وَادِیًا‘‘.اور مفردات راغب میں ہے کہ وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہو اور اسی وجہ سے پہاڑوں کی درمیانی فراخ جگہ کو وادی کہتے ہیں.(اقرب) اَلسَّیْلَ.اَلْمَاءُ الْکَثِیْرُ.بہت پانی.وَالْعَرَبُ تَقُوْلُ ’’سَالَ بِہِمُ السَّیْلُ وَجَاشَ بِنَا البَحْرُ‘‘ اَیْ وَقَعُوْا فِیْ اَمْرٍ شَدِیْدٍ وَنَحْنُ فِیْ اَشَدِّ مِنْہُ.اور عرب سَالَ بِہِمُ السَّیْلُ وَجَاشَ بِنَا الْبَحْرُ کا محاورہ بولتے ہیں جس کے معنے ہیںکہ دوسرے لوگوں کو کثرت پانی نے بہایا.اور ہم پر سمندر نے جوش مارا.اور مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ بھی مصیبت میں مبتلا ہوئے لیکن ہم اُن سے بڑھ کر مصائب میں مبتلا ہوئے.اس محاورہ میں السَّیْلُ کا لفظ مصیبت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے.(اقرب) الزَّبَدُ.مَایَعْلُوالْمَآءَ وَغَیْرَہٗ مِنَ الرَّغْوَۃِ.جھاگ.اَلْخَبَثُ.بری چیز.وَقَوْلُ الْحَرِیْرِیِّ ثُمَّ اَقْبَلْنَا عَلَی الْحَدِیْثِ نَمْـخَضُ زُبَدَہٗ وَنُلْقِیْ زَبَدَہٗ کَنَی بِالزُّبَدِ وَھِیَ جَمْعُ زُبْدَۃٍ عَنْ خِیَارِ الْکَلَامِ وَبِالزَّبَدِ عَمَّا لَاخَیْرَ فِیْہِ.اور حریری نے اپنے اس قول میں زُبد اور زَبَد کا استعمال کیا ہے.زُبد سے مراد اعلیٰ درجہ کا کلام ہے اور زَبَد کے معنے ہیں وہ کلام جس میں کوئی خوبی نہ ہو.(اقرب) رَابِیًا.رَبَا یَرْبُوْ.اَلمَالُ.زَادَ وَ نَمَا.مال زیادہ ہوا اور بڑھا.فُلَانٌ الرَّابِیَۃَ.عَلَاھَا.ٹیلے پر چڑھا.اَلْفَرَسُ رَبْوًا.اِنْتَفَخَ مِنْ عَدْوٍ اَوْ فَزْعٍ وَاَخَذَہُ الرَّبْوَ.گھوڑے کو دوڑ کی وجہ سے سانس چڑھ گیا.فُلَانٌ السَّوِیْقَ.صَبَّ عَلَیْہِ الْمَآءَ فَانْتَفَخَ.ستوؤں کو پانی میں بھگویا تو وہ پھول گئے.فِیْ حِـجْرِہِ.رَبْوًا وَ رُبُوًّا.نَشَأَ.فلاں کی گود میں پلا.وَکَلَّمْتُہٗ فَمَارَبا بِرَأْسِہٖ.اَیْ لَمْ یَعْبَأْبِیْ.میں نے اس سے بات کی لیکن اس نے توجہ نہ کی.الرَّابِیَۃُ مَاارْتَفَعَ مِنَ الْاَرْضِ.ٹیلہ اَخْذَۃً رَّابِیَۃً.شَدِیْدَۃً.سختی سے پکڑنا.(اقرب) پس زَبَدًا رَّابِیًا کے معنے ہوں گے اوپر آنے والی جھاگ.(۲)پھولنے والی جھاگ.(۳)ناقابل توجہ جھاگ یعنی حقیر.جُفَاءً.مَانَفَاہُ السَّیْلُ اِذَا رَمٰی بِہٖ.جس کو سیلاب پھینک دیتا ہے.قَالَ ابْنُ السِّکِّیْتِ.وَذَھَبَ الزّبَدُ جُفَاءً اَیْ مَدْفُوْعًا عَنْ مَائِہٖ.اور ابن سکیت نے ذَھَبَ الزَّبَدُ جُفَاءً میں جُفَاءً کے معنے کئے ہیں پانی سے ہٹائی ہوئی.دور کی ہوئی.پھینکی ہوئی.اَلْبَاطِلُ تَشْبِیْہًا لَہٗ بِزَبَدِ الْقِدْرِ الَّذِیْ لَایُنْتَفَعُ بِہٖ.باطل بے حقیقت.بے فائدہ.چونکہ ہنڈیا کی جھاگ بھی بے فائدہ جاتی ہے اس لئے باطل کو اس پر قیاس کرلیا کیونکہ وہ بھی بے فائدہ ہے اس لئے جفاء کا لفظ اس کے لئے استعمال کرلیا.(اقرب) تفسیر.اس جگہ اس مضمون کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے.کہ پانی جب آسمان سے اترتا
Page 53
ہے اور مختلف راستوں سے بہہ پڑتا ہے تو اس وقت ان گلیوں میں جو پہلے بظاہر صاف معلوم ہوتی تھیں پانی کے گزرتے وقت اس قدر جھاگ پیدا ہوتی اور میل اٹھتی ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے اور شروع شروع میں تو جھاگ کی اس قدر کثرت ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا جھاگ ہی جھاگ ہے.مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ سمٹ کر صرف کناروں پر تھوڑی تھوڑی رہ جاتی ہے اور پانی کا غلبہ ظاہر ہو جاتا ہے.دوسری مثال یہ دی کہ زیور بنانے کے لئے یا برتن وغیرہ بنانے کے لئے معدنیات کو پگھلایا جاتا ہے تو ان کے اوپر بھی ایسی ہی جھاگ آجاتی ہے مگر سنار یا ٹھٹھیارا اس کو صاف کرلیتا ہے اور نیچے سونا یا دوسری کارآمد اشیاء ہی رہ جاتی ہیں.حق کی مثال پانی سے اور باطل کی مثال جھاگ سے دی ہے اس جگہ پر حق کی مثال پانی سے اور باطل کی مثال جھاگ سے دی ہے جو حق پر غالب نظر آتی ہے.یعنی ابتداءً لوگ باطل کی کثرت اور غلبہ کو دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ اسی کا زور دنیا میں ہے مگر انجام کار جھاگ مٹ جاتی ہے اور اصل پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے.حق کی مثال سونے سے یا دوسری معدنیات سے اسی طرح حق کی مثال سونے یا دوسری معدنیات سے دی ہے کہ جن کو پگھلانے پر کچھ میل نکلتی ہے لیکن اس میل کو پھینک دیا جاتا ہے اور صرف معدن کو الگ نکال کر رکھ لیا جاتا ہے.کفار کو بتایا کہ بے شک تم اس وقت جھاگ کی طرح اٹھ رہے ہو اور غالب نظر آتے ہو اور اسلام کا سونا تمہارے نیچے دبا ہوا نظروں سے اوجھل ہورہا ہے مگر جب ہماری نصرت کی ہوائیں چلیں گی تو جھاگ ہی کی طرح بیٹھ جاؤ گے.اور حق کا غلبہ نظر آئے گا اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی باقی رہ جائے گی.یا اس کا یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ فطرت انسانی کو تو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا ہے لیکن اس میں رسم و رواج کا گند مل کر اسے خراب کر دیتا ہے.اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعہ سے پھر فطرت کے پاک تقاضوں کو جگا دیتا ہے اور طبائع میں ایک ایسا جوش پیدا کر دیتا ہے کہ جس طرح تیز بھٹی یا بڑھتے ہوئے سیلاب میں ہوتا ہے اس ہیجان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبائع کا جمود جاتا رہتا ہے.ایک طرف فطرت میں بیداری پیدا ہوجاتی ہے.دوسری طرف رسوم و عادات کی محبت میں جوش آتا ہے اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے فطرت صحیحہ اور رسوم و عادات کے ایک ملے جلے ڈلے کے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں اور انسان کچھ عرصہ کے لئے دو متضاد جذبات کا حامل ہو جاتا ہے.آخر جس کی فطرت زیادہ پاک ہوتی ہے وہ رسوم و عادات کی میل کو باہر نکال کر پھینک دینے میں کامیاب ہوجاتا ہے.اور جو سچی کوشش نہیں کرتا اس کی طبیعت پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پھر رسوم و عادات کی جھاگ فطرت کے سونے سے مل کر پہلے کی طرح
Page 54
ایک ناصاف ڈلا بن کر رہ جاتی ہے.تعلیم انسانی ظرف کے مطابق ہوتی ہے بِقَدَرِهَا کے الفاظ سے یہ بتایا کہ اشاعت تعلیم انسانی ظرف کے مطابق ہوتی ہے.جس کا قلب وسیع اور سلیم ہوگا وہ زیادہ حصہ لے گا.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن کریم بدی اور نیکی کو ممتاز کرکے دکھادے گا اور جب دونوں کا فرق لوگوں پر روشن ہوجائے گا تو اچھے لوگ خود ہی بدی کو پرے اٹھا کر پھینک دیں گے اور نیکی کواختیار کرلیں گے.لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ١ؔؕ وَ الَّذِيْنَ لَمْ اور جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا ان کے لئے کامیابی( مقدر) ہے.اور جنہوں نے يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّ مِثْلَهٗ اس کا کہا نہیں مانا (ان کی یہ حالت ہوگی کہ )اگر جو کچھ بھی زمین میں ہے (سب) ان کے لئے ہوتا اور اس کے برابر مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ١ؕ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ١ۙ۬ اور بھی تو وہ اسے دے کر( اپنے آپ کو )چھڑا لیتے.ان کے لئے بہت ہی برا عذاب (مقدر) ہے وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ١ؕ وَ بِئْسَ الْمِهَادُؒ۰۰۱۹ اور ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.حلّ لُغَات.اِسْتَجَابُوْا.اِسْتَجَابَ سے مضارع ہے اور اِسْتَجَابَ لَہٗ وَمِنْہُ کے معنے ہیں قَبِلَ دُعَاءَ ہٗ اس کی دعا قبول کی.(اقرب) پس اِسْتَجَابُوْا کے معنے ہوں گے بات قبول کی.کہا مانا.اَلْحُسْنٰی.ضِدُّ السُّوأَی.حُسْنٰی.سُوْی.یعنی برائی کے مقابل کا لفظ ہے اور اس کے معنے ہیں اَلْعَاقِبَۃُ الْحَسَنَۃُ.اچھا انجام.اَلظَّفَرُ کامیابی.(اقرب) اِفْتَدَوْا.اِفْتَدٰی سے ہے اور اِفْتَدٰی کے معنے ہیں اِسْتَنْقَذَہٗ بِمَالٍ وَقِیْلَ اَعْطٰی شَیْئًا فَاَنْقَذَہٗ.مال یا کچھ اور بدلہ میں دے کر چھڑا لیا.اَلْمَرْأَۃُ نَفْسَہَا مِنْ زَوْجِھَا اَعْطَتْہُ مَالًا حَتّی تَخَلَّصَتْ مِنْہُ بِالطَّلَاقِ.عورت نے خاوند کو مال دے کر خلاصی حاصل کی اور طلاق لی (اقرب).پس اِفْتَدُوْا کے معنے ہوں گے انہوں نے
Page 55
فدیۃً کچھ دے کر اپنے نفوس کو چھڑانے کی کوشش کی.جَھَنَّم.دَارُالْعِقَاب کا نام ہے.یہ ممنوع من الصرف ہے.بعض کے نزدیک یہ لفظ عجمی ہے.بعض اسے اصل میں فارسی یا عبرانی قرار دیتے ہیں لیکن یہ درست نہیں کہ عربی کے الفاظ کو غیرزبانوں کی طرف منسوب کیا جائے.بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لفظ ایسے قاعدہ سے بنایا گیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی.اس وجہ سے اس کو انہوں نے غیرزبان کا قرار دے دیا.عربی میں جَھَنَ.جَھُوْنًا کے معنے قَرُبَ وَدَنَا کے ہوتے ہیں اوراِس سے جھنم بنا ہے یا یہ لفظ جَھَمَ سے بنا ہے.عربی زبان میں زِیَادَۃُ نُونٍ فِیْ وَسْطِ الْکَلِمَۃِ کی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں.پس جَھَمَ سے جَھَنَّمْ کا بننا خلاف قواعد نہیں اور جَھَمَ کے معنے ہیں اِسْتَقْبَلَہٗ بِوَجْہٍ مُکْفَھِرٍّ.کہ اس کو تیوری چڑھا کر…… ملا اور تَـجَھَّمَہٗ کے معنے ہیں اِسْتَقْبَلَہٗ بِوَجْہٍ کَرِیْہٍ برے چہرے سے ملا.(اقرب) پس جَھَنَّمَ کے معنے ہوئے ایک ناپسندیدہ جگہ جو ناراضگی سے لینے کو بڑھتی ہے.یہ نام اُس کے شعلے مارنے کی وجہ سے رکھا گیا.اَلْمِہَادُ.اَلْفِرَاشُ.بچھونا.اَلْاَرْضُ.زمین.اس کی جمع اَمْھِدَۃٌ ہے.(اقرب) تفسیر.فرمایا جو لوگ اپنے رب کی باتوں کو قبول کریں گے ان کے لئے حُسْنٰی ہوگی یعنی ان کا انجام نیک ہوگا.وہ دیدار الٰہی کریں گے.انہیں کامیابی حاصل ہوگی.اور ان کی عقلوں میں روشنی پیدا کردی جائے گی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانیں گے قرآن مجید کی اطاعت نہ کریں گے ان کی حالتیں گرتی ہی چلی جائیں گے.یہاں تک کہ وہ ایسی مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اگر وہ زمین اور اس کی چیزیں اور اس کی مانند اور چیزیں فدیہ میں دے سکتے تو ضرور دے دیتے.ان سے جو محاسبہ کیا جائے گا وہ ان کے لئے سخت تکلیف دہ ہوگا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا اور وہ بہت بری اور تکلیفوں کی جگہ ہے.سُوْٓءُ الْحِسَابِ کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے حساب میں خرابی کی جائے گی بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان کے اعمال کے نتائج خراب نکلیں گے اور وہ ان طاقتوں کا حساب نہیں پیش کرسکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی کے لئے دیں.مگر انہوں نے غلط استعمال سے ضائع کر دیں.بِئْسَ الْمِهَادُ.میں بتایا کہ اگرچہ جہنم شفاخانہ ہے اور وہاں حصول صحت کی خاطر رکھا جائے گا مگر تاہم وہ تکلیف کا مقام ہے.خلاصہ یہ کہ مومن ترقی کرتے جائیں گے اور کافر گرتے جائیں گے اس لئے اے منکرو! تم کب تک نتائج کو دیکھ کر آنکھیں بند کئے رہو گے.کب تک اس نبی کو نہ مانو گے؟ ایک دن دو دن جنبہ داری کرلو گے
Page 56
قوم پروری کرلو گے مگر آخر ایک نہ ایک دن حق قبول کرنے پر مجبور ہوجاؤگے.اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ جو شخص جانتا ہے کہ جو (کلام) تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ بالکل حق ہے.کیا وہ اس اَعْمٰى ١ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِۙ۰۰۲۰ شخص جیسا (ہو سکتا) ہے جو اندھا ہے.عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں.حلّ لُغَات.یَتَذَکَّرُ.تَذَکَّرَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور تَذَکَّرَ کے معنے ہیں ذَکَرَ الشَّیْءُ وَحَفَظَہٗ فِیْ ذِھْنِہٖ.کسی چیز کو ذہن میں محفوظ کیا یعنی یاد کیا.مَاکَانَ قَدْنَسِیَ نَطَقَ بِہٖ بھولی ہوئی بات کو بیان کیا.اللہَ: مَـجَّدَہٗ وَسَبَّـحَہٗ.اللہ کی بزرگی بیان کی اور اس کی تسبیح کی.(اقرب) اَلْاَلْبَابُ اَلْاَلْبَابُ لُبٌّ کی جمع ہے اس کے معنی عقل کے ہیں.مزید تشریح کے لئے دیکھیں یوسف آیت نمبر ۱۱۲.پس اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ کے معنے ہوں گے کہ صرف عقل والے بات کو سمجھتے ہیں یا عقل والے بات کو یاد رکھتے ہیں یا عقل والے اگر غلطی کر جائیں تو پھر احکام الٰہی کو یاد کرکے سنبھل جاتے ہیں.اَلْاَلْبَابُ.اَللُّبُّ خَالِصُ کُلّ شَیْءٍ.لبّ ہر چیز کے خالص حصہ کو کہتے ہیں.وَالْعَقْلُ.عقل.اَوِالْخَالِصُ مِنَ الشَّوَائِبِ اَوْ مَازَکَی مِنَ الْعَقْلِ.ایسی عقل جو تعصب ضد وغیرہ کی ملاوٹوں سے خالص ہو یا اعلیٰ پایہ کی ہو.فَکُلُّ لُبٍّ عَقْلٌ وَلَا عَکْسَ پس جب لُبّ کا لفظ بولیں تو اس کے معنے عقل کے کرسکتے ہیں لیکن ہمیشہ عقل کے لفظ پر لُبّ کا اطلاق نہیں ہوسکتا.وَ مَعْنَاھَا الْقَلْبُ لُبّ کے ایک معنی دل کے بھی ہیں.اس کی جمع اَلْبَابٌ.أَلُبٌّ اور اَلْبُبٌ آتی ہے.(اقرب) اُولُوالْاَلْبَابِ کے معنے یہ ہوں گے کہ ایسی عقل والے لوگ جو اسے ضد و تعصب وغیرہ سے علیحدہ رکھتے ہیں اور بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں.تفسیر.اس تعلیم کے ذریعہ سے ہر قسم کی ترقیات ملیں گی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ تعلیم اس قسم کی ہے کہ اس کے ذریعہ سے ہر قسم کی ترقیات انسانوں کو ملیں گی.پس جو شخص اس کو سمجھ لیتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہوسکتا ہے جو اندھا ہے.
Page 57
جب دو چیزوں میں مقابلہ کیا جائے تو ہمیشہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے مذکور ہو اس کو دوسری پر قیاس کیا جاتا ہے.اگر پہلی اچھی ہو تو مراد یہ ہے کہ کیا یہ شئے بری شئے کی طرح مضر ہوسکتی ہے اور اگر پہلے بری مذکور ہو تو یہ مراد ہوتی ہے کہ کیا یہ بری شئے اچھی چیز کی طرح فوائد پیدا کرسکتی ہے.مثلاً اگر یہ کہیں کہ کیا اندھا آنکھوں والے کے برابر ہوسکتا ہے تو اس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ وہ آرام اور فوائد جو آنکھوں والے کو حاصل ہیں وہ اندھے کو نہیں حاصل ہوسکتے اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا آنکھوں والا اندھے کی طرح ہوسکتا ہے تو اس وقت زور اس بات پر ہوتا ہے کہ اندھے کو جو تکالیف پہنچتی ہیں کیا وہی آنکھوں والے کو پہنچ سکتی ہیں.پس اس آیت میں اس پر زور ہے کہ مسلمان کسی طرح بھی ان نقصانات میں مبتلا نہیں ہوسکتے جو کفار کو پہنچ سکتے ہیں.اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ میں ایک نیا مضمون بیان کیا ہے.فرماتا ہے اس تعلیم سے وہی لوگ نصیحت و نفع حاصل کرتے ہیں جو اولوالالباب ہیں.یعنی جو دینی لب اور عقل رکھتے ہیں یہ مقابلہ جو پیچھے مسلمانوں اور کافروں کی حالت کا کیا گیا ہے اس سے نفع حاصل کرنا عقلمندوں کا کام ہے.جو دینی عقل کو مار دیتا ہے اور اسے ضائع کر دیتا ہے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے.پس دین کی باتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے عقل کو محفوظ رکھنا اور اسے عادات و جذبات سے کند نہ ہونے دینا ضروری ہوتا ہے مگر افسوس کہ اکثر لوگ اس قیمتی جوہر کو عادات و جذبات کے پردوں میں چھپاد یتے ہیں اور بظاہر انسان لیکن بباطن حیوان ہوتے ہیں.کاش کوئی اس پر غور کرے اور فائدہ اٹھائے.الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَۙ۰۰۲۱ جو اللہ( تعالیٰ) کے( ساتھ کئے ہوئے) عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس پختہ عہد کو نہیں توڑتے.حلّ لُغَات.اَلْعَہْدُ.اَلْوَصِیَّۃُ.وصیت.اَلْیَمِیْنُ یَحْلِفُ بِھَا الرَّجُلُ.قسم.اَلْمَوْثِقُ.پختہ بات.اَلْمِیْثَاقُ.پختہ اقرار.اَلَّذِیْ یَکْتُبُہٗ وَلِیُّ الْاَمْرِ لِلْوُلَاۃِ اِیْذَانًا بِتَوْلِیَتِھِمْ.بادشاہ اپنے ماتحت افسران کو جو ان کی تقرری کا حکم نامہ لکھ کر دیتا ہے.(اقرب) تفسیر.چونکہ باوجود اس کے کہ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے عقل کا مادہ رکھا ہے.لوگ عام طور پر اس کو استعمال نہیں کرتے اور عدم استعمال کی وجہ سے اسے بالکل مار دیتے ہیں.مگر باوجود اس کے اس امر کے مدعی ہوتے
Page 58
ہیں کہ وہ عقلمند ہیں.اللہ تعالیٰ اولوالالباب کی علامات بیان فرماتا ہے تاکہ انسان اس مخفی جوہر کو اس کی علامتوں کے ذریعہ سے پہچان سکے.عقل مندوں کی پہلی علامت پہلی علامت یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت شناس ہوتے ہیں اور چھلکے کے پیچھے پڑنے سے اپنے آپ کو روک دیتے ہیں اس عہد کو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باندھا ہے کامل طور پر پورا کرتے ہیں.عقل کا کام یہی ہے کہ وہ موازنہ کرتی ہے اور جو اعلیٰ شیئے ہو اس کو قبول کرلیتی اور جو ادنیٰ شیئے ہو اسے رد کردیتی ہے.پس یہ لوگ اس امر کو دیکھ کر کہ سب برکت اللہ تعالیٰ کے عہد کے پورا کرنے میں ہے ہمہ تن اس عہد کو پورا کرنے میں مشغول ہوجاتے ہیں.اور دوسرے سب امور کو اس عہد کے تابع کر دیتے ہیں.اگر وہ اس عہد کے مطابق ہوں تو انہیں اختیار کرتے ہیں اور اگر خلاف ہوں تو انہیں رد کردیتے ہیں اور عہد کو ٹوٹنے نہیں دیتے.وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يَخْشَوْنَ اور جو( لوگ) کہ ان تعلقات کو قائم کرتے ہیں جن کے قائم کرنے کا اللہ (تعالیٰ )نے حکم دیا ہے.اور اپنے رب رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِؕ۰۰۲۲ سے ڈرتے ہیں اور برے (انجام والے) حساب سے خوف رکھتے ہیں.حلّ لُغَات.یَصِلُوْنَ وَصَلَ سے ہے اور وَصَلَ الشَّیْءَ بِالشَّیْءِ کے معنے ہیں.لَأَ مَہٗ وَجَمَعَہٗ ضِدُّ فَصَلَہٗ.کسی چیز کو ملایا.جوڑا.(اقرب) پس يَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ کے معنے ہوں گے کہ ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جن کے قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے.اَلْخَشْیَۃُ یَخْشَوْنَ رَبِّھُمْ.یَخْشَوْنَ خَشِیَ سے ہے اور اَلْخَشْیَۃُ کے معنے ہیں خوف یَشُوْبُہٗ تَعْظِیْمٌ وَاَکْثَرُ مَایَکُوْن ذٰلِکَ عَنْ عِلْمٍ بِمَا یُخْشٰی مِنْہُ وَلِذٰلِکَ خُصَّ الْعُلَمَاءُ بِھَا فِی قَوْلِہٖ اِنَّمَا یَخْشَی اللہَ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَمَاءُ.یعنی خشیت اس خوف کو کہتے ہی جس میں اس شخص کی جس سے خشیت کی جائے تعظیم بھی ملی ہوئی ہو اور اس کی بزرگی کا احساس بھی ہو.اور لفظ خشیت کا اکثر استعمال اس جگہ ہوتا ہے جہاں خوف کی وجہ کا بھی علم ہو.یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت صرف اس کے عالم بندوں کے دل میں ہوتی ہے.ورنہ خوف تو عام
Page 59
لوگوں کے دل میں بھی ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے (مفردات) پس يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ کے معنے ہوں گے کہ وہ اپنے رب سے ایسی خشیت کرتے ہیں جس میں اس کی تعظیم اور بزرگی پائی جاتی ہے اور وہ علم پر مبنی ہوتی ہے.تفسیر.عقل مندوں کی دوسری علامت دوسری علامت عقلمندوں کی یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کی پابندی کے بعد اور اس سے کامل تعلق پیدا کرلینے کے بعد اس کے ان بندوں کی طرف جھکتے ہیں جن سے تعلق رکھنے کا اس نے حکم دیا ہے.مثلاً اللہ تعالیٰ کے رسول، ملائکہ، خلفاء پھر اولیاء و ابرار اور اس کے بعد تمام مخلوقات حسب مراتب مثلاً قومی نظام کے چلانے والے رشتہ دار، محسن ہمسائے، غرباء و مساکین اہل وطن، مسافر باقی افراد انسانیت، حیوانات جن سے وہ کام لیتا ہے اور پھر تمام چرند پرند حتیٰ کہ درندے اور کیڑے مکوڑے پھر نباتات اور جمادات غرض تعلق باللہ کے بعد عقلمند انسان کا کام ہے کہ جن جن چیزوں سے اور جس جس حد تک اللہ تعالیٰ نے تعلق کا حکم دیا ہے اس حد تک اور اس صورت میں ان سے تعلق رکھے.اس علامت میں گویا شفقت علی خلق اللہ اور مادی اسباب سے استمداد اور ان کے استعمال کا ذکر کیا ہے اور یہ نکتہ بتایا ہے کہ عقلمند وہ نہیں جو دنیا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی جستجو کرتا ہے بلکہ عقلمند وہ ہے جو خدا تعالیٰ کو پاکر اس کے ارشاد کے ماتحت دنیا کی طرف جھکتا ہے.اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتی ہے کہ دَنَا فَتَدَلّٰى.فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى (النجم :۹،۱۰) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو خدا تعالیٰ کے قریب ہوئے.پھر اس کے حکم کے ماتحت اس مقام سے اتر کر مخلوق کی طرف جھکے.اور شفقت علی خلق اللہ کا اعلیٰ نمونہ دکھایا اور خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ بن گئے.جس طرح کمان کا چلہ ہوتا ہے کہ ایک سرا ایک طرف اور ایک سرا ایک طرف بندھا ہوا ہوتا ہے.اس آیت میں لطیف پیرایہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوشش کا ذکر کیا ہے جو آپؐ نے بنی نوع انسان کو خدا تعالیٰ سے ملانے کے لئے کی.لیکن چونکہ یہ موقع اس آیت کی تفسیر کا نہیں میں نے درمیانی مطالب کو ترک کرکے صرف نتیجہ بیان کر دیا ہے.غرض آیت زیر تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے عقلمندوں کی دوسری علامت یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور محبت میں کمال حاصل کرکے اس کے حکم اور اس کی ہدایت کے ماتحت مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.اور مخلوق سے رشتہ اتحاد و اخوت اور احسان جوڑتے ہیں.عقل مندوں کی تیسری علامت تیسری علامت یہ بتائی ہے کہ عقلمند لوگ اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتے ہیں.
Page 60
خشیت کے معنی جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے خشیت کسی اعلیٰ صفات والی چیز کے کمال و حسن کو پہچاننے کے بعد اس کے ہاتھ سے جاتے رہنے کے خوف کو کہتے ہیں.خشیت کے لفظ میں اس چیز کی معرفت کا بھی مفہوم ہے جس سے خوف کیا گیا ہو گویا خشیت کا لفظ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ اس چیز کی معرفت حاصل ہو جس سے خوف کیا گیا ہو.نیز خوف نقصان یا ضرر کا نہ ہو بلکہ اس وجہ سے ہو کہ انسان یقین کرے کہ وہ چیز نہایت اعلیٰ اور عظمت والی ہے.ایسا نہ ہو کہ اپنی کسی غفلت کی وجہ سے میں اس کا قرب کھو بیٹھوں.پس اللہ تعالیٰ کی خشیت کے یہ معنے ہوئے کہ جب تعلق باللہ کے مقام کو انسان حاصل کرلیتا ہے تو چونکہ اس پر کھل جاتا ہے کہ یہی مقام انسان کی حقیقی راحت اور کمال کا مقام ہے وہ اس کے جاتے رہنے کے خیال کو بھی برداشت نہیں کرسکتا.اور ہر وقت اس کی حفاظت کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور پوری طرح اس کا خیال رکھتا ہے.کہ جو مقام قرب اسے حاصل ہوا ہے وہ کسی غفلت کی وجہ سے کھویا نہ جائے.اسی علامت کا دوسرا حصہ یہ بتایا ہے کہ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ یعنی ایک طرف اگر اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام کی حفاظت کا خیال دامنگیر ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ اس امر سے بھی خائف رہتا ہے کہ شفقت علی خلق اللہ کا جو مقام اسے حاصل تھا اس میں کسی کو تاہی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستوجب نہ ہو جائے.پہلی دو علامتوں میں چونکہ تعلق باللہ کو اصل اور شفقت علی خلق اللہ کو اس کا نتیجہ قرار دیا تھا.تیسری دلیل میں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے تعلق کے نقص کے لئے خشیت کا لفظ اور مخلوق کے تعلق کے نقص کے متعلق خوف کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اول الذکر لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جس چیز سے ڈرا جاتا ہے وہ مقصود بالذات ہے اور خوف کا لفظ ضروری نہیں کہ مقصود بالذات کے لئے بولا جائے بلکہ بسا اوقات یہ لفظ ایسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جس سے دور بھاگنا مقصود ہو.گو کبھی مقصود بالذات شئے کی ناراضگی کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے.وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اور جنہوں نے اپنےرب کی رضا کی طلب میں ثابت قدمی سے کام لیا اور نماز کو عمدگی سے ادا کیا اور جو (کچھ )ہم نے اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ انہیں دیا ہےاس میں سے چھپ کر (بھی) اور ظاہر( بھی ہماری راہ میں) خرچ کیا اور( جو) بدی کو نیکی کے ذریعہ دور
Page 61
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِۙ۰۰۲۳ کرتے ہیں انہی کے لئے اس گھر کا( بہترین) انجام (مقدر) ہے.حلّ لُغَات.صَبَرُوْا.صَبَرَ سے جمع کا صیغہ ہے اور صبر کے معنے ہیں تَرْکُ الشَّکْوٰی مِنْ اَلَمِ الْبَلْوٰی لِغَیْرِاللہِ لَا اِلَی اللہِ کہ مصیبت کے دکھ کا شکویٰ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہ کرنا.فَاِذَا دَعَا اللہَ اَلْعَبْدُ فِیْ کَشْفِ الضُّرِّ عَنْہُ لَا یُقْدَحُ فِیْ صَبْرِہٖ.اگر بندہ اپنی رفع مصیبت کے لئے خدا تعالیٰ کے پاس فریاد کرے تو اس کے صبر پر اعتراض نہ کیا جائے گا.وَقَالَ فِی الْکُلّیّاتِ اَلصَّبْرُ فِی الْمُصِیْبَۃِ.اور کلیات میں لکھا ہے کہ صبر مصیبت کے وقت ہوتا ہے.وَصَبَرَ الرَّجُلُ عَلَی الْاَمْرِ نَقِیْضُ جَزِعَ اَیْ جَرُؤَ وَشَجُعَ وَتَجَلَّدَ اور صبر جزع یعنی شکویٰ کرنے اور گھبرانے کے مقابل کا لفظ ہے اور صبر کے معنے ہوتے ہیں دلیری دکھائی.جرأت دکھائی.ہمت دکھائی.اور صَبَرَ عَنِ الشَّیْءِ کے معنے ہیں اَمْسَکَ عَنْہُ کسی چیز سے رکا رہا.اَلدَّابَۃُ حَبَسَہَا بِلَاعَلَفٍ.اور صبر کا مفعول دابۃ ہو تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ جانور کو بغیر چارہ دینے کے روکے رکھا.صَبَرْتُ نَفْسِیْ عَلٰی کَذَا کے معنے ہیں میں نے اپنے نفس کو کسی چیز پر قائم رکھا یا کسی چیز سے روکے رکھا.چنانچہ انہی معنوں میں صَبَرْتُ عَلَی مَااَکْرَہٗ وَصَبَرْتُ عَمَّا اُحِبُّ کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ تکلیف دہ حالت پر میں نے نفس کو استقلال سے قائم رکھا اور پسندیدہ امور سے نفس کو باز رکھا.صبر کے تین معنی گویا صبر کے تین معنے ہوئے گناہ سے بچنا اور اپنے نفس کو اس سے روکے رکھنا.(۲)نیک اعمال پر استقلال سے قائم رہنا.(۳)جزع فزع سے بچنا.(اقرب) اور وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ کے معنے ہوں گے جو اپنے رب کی رضا کے لئے جزع فزع سے بچے.بدیوں سے رکتے رہے اور نیکیوں پر ہمت سے قائم رہے.یَدْرَءُوْنَ.دَرَأَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور دَرَأَ کے معنے ہیں دَفَعَہٗ وَقِیْلَ دَفَعَہٗ شَدِیْدًا.اس کو ہٹایا اور بعض کہتے ہیں کہ دَرَأَ میں سختی سے ہٹانے کے معنے پائے جاتے ہیں.(اقرب) اور یَدْرَءُوْنَ کے معنی ہوں گے سختی سے ہٹاتے ہیں.عُقْبٰی.جَزَآءُ الْاَمْرِ.کام کی جزا.اٰخِرُ کُلَّ شَیْءٍ.ہر چیز کا آخر، انجام.اَلْاٰخِرَۃُ.آخرت.(اقرب) اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ کے معنے ہوں گے.انہی کے لئے اس آخرت کے گھرکا بہترین انجام مقدر ہے.
Page 62
تفسیر.اولوالالباب کی چار اور علامتیں اس آیت میں چار اور علامات اولوالالباب کی بیان فرمائی ہیں.پہلی وجہ جو پچھلی آیات کو ملا کر چوتھی ہے یہ بتائی ہے کہ وہ لوگ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لئے صبر کرتے ہیں جیسا کہ حل لغات سے ظاہر ہے صبر کے تین معنی ہیں.صبر کے تین معنے (۱) گناہ سے بچنا اور جذبات کو بری راہ پر پڑنے سے روکنا (۲)نیک اعمال پر استقلال سے قائم رہنا.(۳)جزع فزع سے بچنا.پس اس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ چوتھی علامت عقلمندوں کی یہ ہے کہ وہ بدی سے مجتنب رہتے ہیں.نیکی پر قائم رہتے ہیں اور جزع فزع سے رکتے ہیں اور اسی پر کفایت نہیں کرتے بلکہ اپنی نیتوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں.اور ان کا یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے ہوتا ہے نہ کہ کسی ذاتی یا قومی غرض کے ماتحت یا کسی طبعی نقص کے سبب.یعنی ان کا صبر کم ہمتی یا کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے نہیں ہوتا.نہ اپنے ذاتی اور قومی فوائد کے حصول کے لئے ہوتا ہے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے.باوجود طاقت انتقام کے وہ صبر کرتے ہیں اور اس میں ان کے مدنظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے.بدی کی طاقت رکھتے ہوئے اس سے بچنا اصل عفت ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عفت اس شخص کی نہیں جس کے اندر گناہ کی طاقت نہیں.عفت تو اسی کی ہے جس کے اندر بدی کی طاقت ہے اور بدی کی طاقت کے ہوتے ہوے وہ بدی سے مجتنب رہتا ہے.جو شخص رات کے وقت ڈر کے مارے اپنے مکان سے باہر نہیں نکل سکتا وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ڈکیتی کا مرتکب نہیں ہوتا.ایک شخص جو کمزور اور نحیف الجثہ ہے وہ اگر ایک مضبوط آدمی سے مار کھا کر کہے کہ میں صبر کرتا ہوں تو وہ صابر نہیں کہلائے گا بلکہ بے بس کہلائے گا.ہاں اگر وہ جرأت اور طاقت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اختیار کرتا ہے تو وہ بے شک صابر کہلانے کا مستحق ہے.(اسلامی اصول کی فلاسفی روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۳۴۰) پانچویں علامت اقاموا الصلوٰۃ ہے پانچویں علامت اَقَامُوا الصَّلٰوةَ کی بیان فرمائی.نمازوں کو باقاعدہ اور باشرائط ادا کرتے ہیں.یعنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات میں باقاعدگی کی عادت ہوتی ہے اور بے استقلالی ان کے اعمال میں نہیں ہوتی.چھٹی علامت خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے چھٹی علامت یہ بتائی وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں.پوشیدہ تو اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ تا دوسرے پر احسان نہ ہو اور علانیہ اس لئے کرتے ہیں کہ تا دوسروں کو صدقہ اور نیکی کی تحریک پیدا ہو اور دوسرے لوگ بھی انہیں
Page 63
دیکھ کر نیکیوں میں حصہ لیں.ساتویں علامت.بدی کو دور کرنے کے چار گر ساتویں علامت يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ بیان فرمائی اور اس میں بدی کو دور کرنے کے یہ گر بتائے ہیں (۱)وہ نیک اعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے نمونہ کو دیکھ کر بدی کو ترک کریں.گویا کہ صرف زبانی وعظ پر بس نہیں کرتے کہ وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا بلکہ عملاً نیکی کا نمونہ دکھاتے ہیں اور اس طرح بدی کی جڑ کھوکھلی کرتے ہیں.(۲)دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ نیک باتوں کا وعظ کرتے ہیں اور اس طرح آپ ہی آپ برائی کا رواج مٹتا جاتا ہے یعنی فحش کی تشریحات پر اتنا زور نہیں دیتے جتنا کہ نیک اعمال کی خوبیوں پر اور اس طرح ذہنوں کو بدی سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف پھیرتے ہیں.(۳)تیسرے معنے یہ ہیں کہ وہ بہتر اور صالح اور مناسب موقعہ اعمال اس غرض کو مدنظر رکھ کر بجالاتے ہیں کہ تا ان کے ذریعہ بدی مٹ جائے.تورات کے مطابق ان کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ ضرور سزا ہی دی جائے اور نہ انجیل کے مطابق ان کی یہ غرض ہوتی ہے کہ ضرور نرمی سے ہی ہر موقعہ پر کام لیا جائے اور ایک گال کے بعد دوسری گال بھی پھیر دی جائے بلکہ ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بدی مٹ جائے.اس غرض کو پورا کرنے کے لئے جو مناسب طریق ہو اسے اختیار کرتے ہیں.اگر سزا سے بدی مٹ سکتی ہے تو وہ سزا دیتے ہیں اور سختی سے کام لیتے ہیں اور اگر نرمی اور عفو کے ساتھ بدی مٹ سکتی ہے تو اس وقت نرمی اور عفو سے بدی کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر عفو کے علاوہ احسان کی ضرورت سمجھتے ہیں تو بدی کے مقابل عفو اور احسان کے ذریعہ بدی کی جڑ کاٹ دیتے ہیں.پس جو بدی کے مٹانے کے لئے بہتر عمل ہو اسے اختیار کرتے ہیں.(۴)چوتھے معنے ا س کے یہ ہوسکتے ہیں کہ وہ شرارت کے مقابلہ میں شرارت سے کام نہیں لیتے.بلکہ ہمیشہ انصاف کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں.ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شرارت کے مقابلہ میں انصاف اور راستی کو چھوڑ دیں.عُقْبَی الدَّار اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ.عقبیٰ عام طورپر عاقبت محمودہ کے معنے میں استعمال ہوتا ہے.یعنی اچھا انجام جس کا برا انجام ہو وہ گویا انجام ہی نہیں سمجھا جاتا.الدار سے مراد جنت ہے کیونکہ اصل گھر وہی ہے.یہ دنیا تو عارضی سفر ہے.پس اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ کے معنے ہوئے کہ آخرۃ میں بہتر انجام انہیں کا ہوگا.
Page 64
جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا۠ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ یعنی مستقل رہائش کے باغات جن میں وہ( خود بھی) داخل ہوں گے اور ان کے بڑوں اور اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ ان کی بیویوں اور ان کی نسلوں میں سے بھی جنہوں نے نیکی اختیار کی ہوگی اور فرشتے مِّنْ كُلِّ بَابٍۚ۰۰۲۴ ہر ایک دروازہ سے ان کے پاس آئیں گے.حلّ لُغَات.جَنّٰتٌ.جَنَّۃٌ کی جمع ہے اور اَلْجَنَّۃُ جَنَّ میں سے ہے.وَاَصْلُ الْجَنِّ سَتْرُ الشَّیْءِ.جَنَّ کے اصل معنے کسی چیز کو ڈھانپنے کے ہیں.یُقَالُ جَنَّہُ اللَّیْلُ چنانچہ جَنَّہُ اللَّیْلُ کا محاورہ انہی معنوں میں مستعمل ہے کہ رات نے اس کو ڈھانپ لیا.وَالْجَنَّۃُ کُلُّ بُسْتَانٍ ذِیْ شَجَرٍ یَسْتُرُ بِاَشْجَارِہِ الْاَرْضَ.اور جنت ہر اُس باغ کو کہتے ہیں جس میں کثرت سے درخت ہوں اور وہ درختوں کے جھنڈ سے زمین کو ڈھانپ لے.وَقَدْ تُسَمَّی الْاَشْجَارُ السَّاتِرَۃُ جَنَّۃً.اور ڈھانپنے اور چھپانے والے یعنی گھنے درختوں کو بھی جَنَّۃٌ کہتے ہیں.وَسُمِّیَتْ الْجَنَّۃُ اِمَّا تَشْبِیْہًا بِالْجَنَّۃِ فِی الْاَرْضِ وَاِنْ کَانَ بَیْنَہُمَا بَوْنٌ.وَ اِمَّا لِسَتْرِہٖ نِعَمَہَا عَنَّا الْمُشَارَ اِلَیْہِ بِقَوْلِہٖ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَااُخْفِیَ لَہُمْ مِنْ قُرَّۃِ اَعْیُنٍ.اور جنت کو اس لئے جنت کے نام سے پکارا گیا ہے کہ یا تو وہ دنیاوی باغات کے مشابہ ہے اگرچہ ان میں اور اس میں بہت فرق ہے.یا اس وجہ سے کہ اس کی نعمتیں ہم سے پوشیدہ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ میں فرمایا ہے کہ جنت کی نعماء کا کسی کو علم نہیں.(مفردات) عَدْنٍ.عَدَنَ بِالْمَکَانِ عَدْ نًا.اَقَامَ بِہٖ.عَدَنَ کے معنے ہیں کسی جگہ میں ٹھہرا.تَوَطَّنَہٗ.اس کو وطن بنایا.وَقِیْلَ مِنْہُ جَنَّاتُ عَدْنٍ اَیْ جَنَّاتُ اِقَامَۃٍ لِمَکَانِ الْخُلُوْدِ اور بعض محققین لغت نے کہا ہے وَجَنّٰتُ عَدْنٍ میں عدن اقامت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ رہ پڑنے کے باغات.کیونکہ ان میں ہمیشہ رہا جائے گا.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ عُقْبَى الدَّارِ سے مراد وہ جنات ہیں کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہیں یا یہ
Page 65
مراد ہے کہ اولوالالباب ہمیشہ رہنے والی جنتوں کے وارث ہوں گے.جنات میں مومنوں کے رشتہ داروں کے داخل کئے جانے کی وجہ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ.اور ان کے ماں باپ اور ازواج اور اولادیں جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنات میں داخل ہوں گے.اس آیت میں ایک عظیم الشان اصلیت اور صداقت کا اظہار اس آیت میں ایک عظیم الشان اصلیت اور صداقت کا اظہار کیا ہے.اس اصل اور صداقت کو صرف قرآن کریم نے ہی بیان کیا ہے.دنیا کی اور کسی کتاب نے اس مسئلہ کو نہیں لیا.دنیا میں کوئی شخص کوئی ایسی نیکی اور بدی نہیں کرتا جس میں دوسرے لوگ کسی نہ کسی رنگ میں شریک نہ ہوں.تاجر کی تجارت کی کامیابی، زراعت پیشہ کی زراعت کی کامیابی سینکڑوں ہزاروں دوسرے افراد کے دانستہ یا نادانستہ تعاون سے وابستہ ہے.یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے اور اس طرح دوسرے لوگوں کا حق دلایا ہے.یہی حال دوسرے کاموں کا ہے.مثلاً فرض کرو ایک شخص تبلیغ کے لئے جاتا ہے.تو اس تبلیغ میں اس کی بیوی کا حصہ بھی ہے کیونکہ وہ اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کے گھر اور اس کے بال بچہ کا انتظام کرتی ہے.ان کی پرورش کرتی ہے.اگر وہ بال بچوں کی حفاظت نہ کرے تو مبلغ کو تبلیغ کے لئے جانے میں بڑی دقت ہوگی.اسی طرح اگر والدین نے اچھی طرح تربیت نہ کی ہوئی ہو تو وہ کس طرح دین کے کاموں میں حصہ لے سکے گا.یا اگر اولاد والدین کو مطمئن نہ بیٹھنے دے تو وہ کس طرح نیکیوں میں حصہ لے سکتے ہیں.مومن کی نیکیوں میں اس کے رشتہ دار بھی شریک ہوتے ہیں پس چونکہ انسان نیکیوں میں ترقی اپنے رشتہ داروں کی مدد سے کرتا ہے اس کے انعام میں ان کا حصہ رکھا.اور یہ قانون مقرر کیا کہ سب خاندان میں جو سب سے اعلیٰ مقام کو حاصل کرے دوسرے سب اس کے پاس ہی رکھے جائیں نہ کہ اپنے چھوٹے مقاموں پر.بشرطیکہ وہ نجات یافتہ ہوں.اس آیت میں زَوج کے معنے ساتھی کے ہیں زَوج کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے میرے نزدیک اس کے یہاں جوڑے کے معنے ہیں.یعنی ساتھی کے نہ کے مرد عورت کے.اور میرے نزدیک اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو نیکیوں میں اس کے ممد اور معاون ہوئے ہوں نہ کہ صرف میاں اور بیوی.اس سے عورتوں کے متعلق بھی سوال حل ہو جاتا ہے کہ وہ نبوت کے مقام پر کیوں نہیں پہنچائی جاتیں کیونکہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ نبی کی بیویوں کو بھی اس مقام پر رکھا جائے گا جس مقام پر نبی ہوں گے یعنی گو ان کی بناوٹ کے لحاظ سے ان کو دنیا میں نبی نہیں بنایا جاتا لیکن وہ انہی انعامات میں شریک ہوں گی جو انبیاء کو ملیں گے.اب دیکھو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو
Page 66
ایک شخص ہیں مگر عورتیں گیارہ ان کے ساتھ ان کے انعامات میں شریک ہوں گی.اسی طرح نبی کا زوج صدیق ہوتا ہے اور عورتوں کو صدیق کے درجہ پانے سے روکا نہیں گیا.اب جو عورتیں صدیقیت کے مقام پر پہنچ جائیں وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائی جائیں گی.جس طرح تمام صدیق پہنچائے جائیں گے.کیونکہ وہ مرتبۂ صدیقیت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہوں گی.وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سے یہ بتانا مطلوب نہیں کہ جنت بڑا مقام ہے اور اس کے بہت سے دروازے ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ اخلاق حسنہ اور نیکیاں کہ جن کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوں گے وہ اس جہان میں جنت کے دروازوں کی شکل میں متمثل ہوں گی.سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِؕ۰۰۲۵ (اور کہیں گے) تمہارے لئے سلامتی ہے.کیونکہ تم ثابت قدم رہے پس( اب دیکھو کہ تمہارے لئے) اس گھر کا کیا ہی اچھاانجام ہے.تفسیر.سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ کہنے کا مطلب ہر دروازہ سے ملائکہسَلٰمٌ عَلَيْكُمْ کہتے ہوئے داخل ہوں گے یعنی ان کو ملائکہ بتائیں گے کہ تم فلاں نیکی کی وجہ سے اس دروازہ سے داخل ہوئے ہو اور فلاں خلق فلاں دروازہ کی شکل میں متمثل ہے اور ان کو سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ کہیں گے.یہ یاد دلانے کے لئے کہ تم نے جو نیکیاں کی تھیں ان کی وجہ سے اب تم پر ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی.جس طرح تم نے ہر رنگ میں نیکی کی تھی اسی طرح اب ہر رنگ میں تم پر سلامتیاں نازل ہوں گی.سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ دوام سلامتی پر دلالت کرتا ہے سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ دوام سلامتی پر دلالت کرتا ہے اور بِمَا صَبَرْتُمْ کہہ کر اس دوام کی وجہ بھی بتادی جو یہ ہے کہ جس طرح تم استقلال سے نیکی پر قائم رہے اور باوجود روکوں کے رکے نہیں.ہم بھی اب دائمی سلامتی تم پر نازل کریں گے.اس آیت میں آریوں کے اس اعتراض کا جواب بھی آجاتا ہے کہ جب عمل محدود ہیں تو ثواب غیرمحدود کس طرح مل سکتا ہے(ستیارتھ پرکاش باب نہم).کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے زندگی بھر نیکی کو نہ چھوڑا تو اپنا فرض ادا کر دیا.موت کا آنا تمہارے بس کی بات نہ تھی.جب تک تمہارا بس تھا تم نے نیکی کے مقام کو نہ چھوڑا اور عمل کرتے رہے.پس اب مجھ پر واجب ہے کہ میں تم کو ہمیشہ کی کامیابی اور سلامتی عطا کروں.
Page 67
جو شخص تھوڑے تھوڑے ابتلاؤں پر گھبرا جاتا ہے وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص تھوڑے تھوڑے ابتلاؤں پر گھبرا جاتا ہے اور حق پر قائم نہیں رہتا وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا.جنت کا وہی شخص مستحق ہوسکتا ہے جو کسی ابتلاء پر گھبرائے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کبھی قطع نہ کرے اور نیکیوں میں برابر لگا رہے.السلام علیکم پر چکڑالویوں کے اعتراض کا جواب چکڑالوی لوگ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو سلام علیکم آتا ہے پھر مسلمان السلام علیکم کیوں کہتے ہیں.السلام علیکم کہنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ تمہیں خاص سلام سننے کا موقعہ دے اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہماری مراد اس سے یہ نہیں ہوتی کہ تم پر سلامتی نازل ہو بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ تم کو وہ سلام سننے کا موقع دے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے.جیسے وہ سلام جس کا ذکر اس آیت میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ خاص سلام کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو عربی کے قاعدہ کے مطابق السلام علیکم ہی کہا جائے گا.اس آیت کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی سلام کا ذکر ہے.مثلاً سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ(الزمر:۷۴).سورہ زمر کے آخر میں ہے اور سورۃ یٰس میں ہے لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّ لَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ.سَلٰمٌ١۫ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ(۵۸،۵۹).پس جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اے بھائی! خدا تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے اور خدا تعالیٰ کے فرشتے حسب وعدہ ہر دروازے سے داخل ہوکر خدا تعالیٰ کا سلام تم کو پہنچائیں.جو اعلیٰ دعا اس طرح سے پہنچتی ہے وہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے سلام سے کہاں پہنچ سکتی ہے؟ پس سلام علیکم کی جگہ السلام علیکم ہی صحیح ہے.وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ اور جو اللہ کے (ساتھ کئے ہوئے) عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس( تعلق) کے قائم کرنے کا يَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي اللہ (تعالیٰ) نے حکم دیا تھا اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں ان کے لئے (اللہ کی جناب سے)
Page 68
الْاَرْضِ١ۙ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ۰۰۲۶ دوری (مقدر) ہے اور( اسی طرح) ان کے لئے برا گھر( مقرر) ہے.حلّ لُغَات.اَللَّعْنَۃُ.لَعَنَہٗ لَعْنًا.طَرَدَہٗ وَاَبْعَدَہُ مِنَ الْخَیْرِ لَعَنَ کے معنے ہیں اس کو دھتکارا اور بھلائی سے دور کیا.محروم کیا.وَاَخْزَاہُ وَسَبَّہٗ.اس کو ذلیل کیا ور اس کو گالی دی.اَللَّعْنَۃُ اِسْمٌ مِّنَ اللَّعْنِ.لَعْنَۃٌ لَعَنَ کا اسم ہے اور اس کے ایک معنی عذاب کے بھی ہیں.(اقرب) تفسیر.نَقَضَ اور عَھْدَاللہِ دونوں کو ملا کر دو باتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے.یعنی نیکیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بدیوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور جن سے تعلق جوڑنے کا خدا نے حکم دیا تھا ان سے قطع کرتے ہیں.یعنی بجائے صلہ رحمی کے قطع رحمی کرتے ہیں.کوئی نظام قومی کو توڑتا ہے کوئی انبیاء کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی بجائے ان کی مخالفت کرتا ہے.کوئی شفقت علی الناس کو چھوڑ دیتا ہے.کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے.یہ سب قطع کرنا ہے ان باتوں کو جن کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے.وصل کے مقابل پر افساد کے لفظ کےرکھنے کی وجہ وَ يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ.وَصل کے مقابلہ میں اِفْسَاد رکھا ہے یعنی صرف یہی نہیں کہ جن سے وصل اور ملاپ کرنے کا خداوند تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے ان سے وصل نہیں کرتے بلکہ بجائے وصل کے وہ ظلم کرنے لگتے ہیں اور قطع تعلق سے بڑھ کر مخالفت شروع کردیتے ہیں.لعنت کے معنے دوری کے ہیں اُولٰٓىِٕكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ.چونکہ وہ خدا سے قطع تعلق کرتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ سے دور کئے جائیں گے.لعنت کے معنی دوری کے ہیں اور لعنت کا لفظ گالی کے طور پر استعمال نہیں ہوا بلکہ اس سے حقیقت بتائی گئی ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے خود قطع تعلق کریں انہیں قرب کس طرح نصیب ہوسکتا ہے؟
Page 69
اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ١ؕ وَ فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ اللہ (تعالیٰ) جس کے لئے پسند کرتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور( جس پر چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے اور یہ( لوگ) الدُّنْيَا١ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌؒ۰۰۲۷ اس ورلی زندگی پر( ہی) خوش ہو گئے ہیں حالانکہ یہ ورلی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض ایک وقتی سامان ہے.حلّ لُغَات.یَقْدِرُ.قَدَرَ سے ہے اور قَدَراللہُ عَلَیْہِ الْاَمْرَ کے معنی ہیں قَضٰی وَحَکَمَ بِہٖ.اللہ نے کسی کام کا فیصلہ کیا.عَلَیْہِ الرِّزْقَ.قَسَمَہٗ.رزق کو تقسیم کیا.ضَیَّقَہٗ رزق کو تنگ کیا.عَلَی الشَّیْءِ.جَمَعَہٗ وَاَمْسَکَہٗ.کسی چیز کو جمع کیا اور اس کو روکے رکھا.(اقرب) پس اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ کے معنی ہوئے اللہ جس پر چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کرتا ہے.تفسیر.یعنی اگر یہ لوگ کہیں کہ دنیا کی ترقی تو ہمیں ملی ہوئی ہے اور اگلے جہان کی موہوم ہے.اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مان لیا تو اگلے جہان کی ترقیات تو خدا جانے ملیں یا نہ ملیں جو کچھ ملا ہوا ہے وہ تو ہاتھ سے جاتا رہے گا.پنجابی کی مثل ہے ’’ایہہ جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا‘‘ یعنی یہ زندگی تو شیریں ہے دوسری زندگی کسی نے دیکھی نہیں.کہ اس کی خاطر اسے تلخ کیا جائے.اس وسوسہ کا جواب یہ دیا کہ دنیا کی دولتیں اور حکومتیں اور ترقیات بھی تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اگر وہ تم سے چھین کر محمد رسول اللہ صلعم اور آپ کے متبعین کو دے دے تو تم اس کو روک نہیں سکتے.بلکہ ہم تم کو بتا چکے ہیں کہ عنقریب ہم یہ نعمتیں مخالفوں سے چھین کر محمد رسول اللہ صلعم کے متبعین کو دے دیں گے.پس ان کے ماننے سے دنیا کے نقصان کا نہیں دنیا کے فائدہ کا ہی احتمال ہے اور اس کے آثار ظاہر ہورہے ہیں.لیکن بفرض محال محمد رسول اللہ صلعم کو مان کر دنیوی نقصان ہوبھی تو بھی اس کی تعلیم میں قائم رہنے والے ایسے اصول مذکور ہیں کہ ان کے مقابل پر دنیا کی نعمتیں حقیقت کیا رکھتی ہیں؟ اس میں بتایا ہے کہ ذہنی اور فکری ترقیات مادی ترقیات سے جبکہ قوتِ عملیہ کو مردہ نہ کر دیا جائے افضل ہوتی ہیں.کیونکہ مادی ترقیات ہمیشہ ان کے تابع ہوتی ہیں.
Page 70
وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ١ؕ اور جن لوگوں نے (تمہارا) انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتارا قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَۖۚ۰۰۲۸ گیا.توکہہ اللہ جسے چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے اور جو(اس کی طرف) مائل ہو اسے اپنی طرف راہنمائی کرتاہے.حل لغات.یَھْدِیْ ھَدٰی سے ہے اور ھَدَاہُ الطَّرِیْقَ وَاِلَیْہِ وَلَہٗ کے معنے ہیں بَیَّنَہٗ لَہٗ وَعَرَّفَہٗ بِہٖ.راستہ دکھایا ، بتایا اور واضح کیا.ھَدَی فُلَانًا.تَقَدَّمَہٗ اس کے آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لے گیا.ھَدَاہُ اللہُ اِلَی الْاِیْمَانِ اَرْشَدَہُ.ایمان کی طرف رہنمائی کی.(اقرب) اَنَابَ.نَابَ سے ہے اور نَابَ اِلَیْہِ کے معنے ہیں رَجَعَ مَرَّۃً بَعْدَ اُخْرَی.بار بار لوٹا.اِلَی اللہِ.تَابَ توبہ کی.نَابَ فُلَانٌ.لَزِمَ الطَّاعَۃَ.اطاعت کو لازم پکڑا (اقرب) يَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ کے معنے ہوں گے جو اس کی طرف مائل ہو اسے اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے.تفسیر.چونکہ پہلی آیت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ رزق چھین بھی سکتا ہے اس پر کفار کا اعتراض بیان کیا کہ جب انہیں خدا تعالیٰ کی ان طاقتوں کی طرف توجہ دلائی جائے تو جھٹ کہتے ہیں کہ بہت اچھا اگر ایسا ہے تو یہ نشان ہمیں دکھاؤ.یعنی ہمارا رزق چھینا جائے تب مانیں.اس کا جواب یہ دیا کہ نشانات تو اللہ تعالیٰ کے بہت نازل ہوئے ہیں لیکن تم ا ن سے فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے اور صرف یہی مطالبہ کرتے ہو کہ تم پر عذاب آئے.گویا رحمت کے نشان علمی نشان، روحانی نشان سب بے حقیقت ہیں.تمہارے نزدیک صرف یہی نشان ماننے کے قابل ہے کہ عذاب آجائے.حالانکہ تباہ کر دینے والا عذاب آنے کے بعد ہدایت کا تو موقعہ ہی باقی نہیں رہتا.پھر اس نشان سے یہ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ پس حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب سے ہلاکت کے مستحق ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے ورنہ ہدایت کے نشانوں سے کیوں فائدہ نہ اٹھاتے.خدا تعالیٰ ہلاک اسی کو کرتا ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے.چونکہ اس جگہ شبہ پیدا ہوسکتا تھا کہ گویا خدا تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ یا ہلاک کر دیتا ہے اس لئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ بلاوجہ نہیں ہلاک کرتا بلکہ اس کی سنت ہے کہ جو اس کی
Page 71
طرف جھکے وہ اسے ہدایت دیتا ہے.ہلاک اسی کو کرتا ہے جو اس سے دور بھاگتا ہے.اور ہدایت قبول کرنے سے خود انکار کردیتا ہے.اس میں ان لوگوں کا رد آگیا جو مشیت کا لفظ دیکھ کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے.خدا تعالیٰ زبردستی گمراہ نہیں کرتا بلکہ صرف اسے گمراہ کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ گمراہ قرار دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہی نہیں.اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ١ؕ اَلَا یعنی جو ایمان لائے ہوں اور ان کے دل اللہ کی یادسے اطمینان پاتے ہوں سنو بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُؕ۰۰۲۹ اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں.حلّ لُغَات.تَطْمَئِنُّ.اِطْـمَأَنَّ سے مضارع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اِطْـمَئَنَّ اِلَی کَذَا کے معنے ہیں سَکَنَ وَاٰمَنَ لَہٗ.سکون پکڑاا ور تسلی پائی.(اقرب)تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ کے معنے ہوں گے دل آرام محسوس کرتے ہیں، دل تسلی پاتے ہیں.تفسیر.اصل مقصود ملنے سے تڑپ دور ہوجاتی ہے لوگ مال کماتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں ان کو اچھی اولاد ملتی ہے، اچھی بیویاں ہوتی ہیں، اچھے دوست ملتے ہیں، تجارت میں فائدہ اٹھاتے ہیں، زراعت میں نفع حاصل کرتے ہیں، علم میں کمال حاصل کرتے ہیں.غرضیکہ ہر چیز میں ترقی کرتے ہیں مگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا.ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دو اور تکلیف دہ خواہشات دل میں پیدا ہوجاتی ہیں اور ہر وقت دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ گویا اصل چیز جس کی انہیں خواہش تھی انہیں ابھی نہیں ملی.جس طرح کہ ایک بچہ جس کی ماں جدا ہو گئی ہو کبھی کسی کی چھاتی سے لگتا ہے کبھی کسی کی چھاتی سے مگر چین کسی جگہ نہیں پاتا.کیونکہ اسے وہ مقصود جس کی اسے تلاش تھی حاصل نہیں ہوا.یعنی اس کی حقیقی ماں اس کو نہیں ملتی.اسی طرح دنیوی ترقی کرنے والے لوگوں کا حال ہوتا ہے.حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا اس کا بچہ گم ہو گیا تھا.وہ جس بچہ کو دیکھتی تھی اسے اپنی چھاتی سے لگا لیتی.پیار کرتی اور پھر اسے چھوڑ کر آگے چلی جاتی.آخر اس کو اپنا بچہ مل گیا ور اسے لے کر اطمینان سے بیٹھ گئی.حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو متوجہ کرکے فرمایا کہ جیسے اس عورت کو
Page 72
اپنے بچے کے مل جانے سے خوشی ہوئی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا گنہگار بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ایک دوسرا سبق آموز پہلو بیان فرمایا ہے.مگر میرا مقصد اس واقعہ کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ اس عورت کو کس قدر تڑپ تھی جب تک اس کا اصلی مقصد نہیں ملا تھا مگر جب مقصود ملا تو اسے اطمینان حاصل ہو گیا.یہی حال ہر انسان کا ہے.اصلی مقصد کے ملنے کے ساتھ ہی تڑپ دور ہوجاتی ہے اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے.انسانی پیدائش کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی یاد اور ذکر ہے پس چونکہ اصل مقصد انسانی پیدائش کا خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر ہی ہے.جب خدا مل جاتا ہے تو کوئی جلن اور تڑپ نہیں رہتی.بلکہ اطمینان ہی رہتا ہے.جو لوگ دنیا کی جستجو میں رہتے ہیں ان کو جس قدر ترقی ملتی ہے ان کی جلن بڑھتی جاتی ہے.مگر جو خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور جس قدر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل کا اطمینان بڑھتا جاتا ہے.اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کی جستجو ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد قرار دیا ہے.پس جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے.ہماری ریاستوں کو ہی دیکھو.باوجودیکہ ان کی حفاظت گورنمنٹ کے ذریعہ ہے مگر بعض رؤسا کے ڈر کا یہ حال ہے کہ ولایت سے بند ہوکر پانی آتا ہے.ان کے سامنے کھولا جاتا ہے.پھر بھی پہلے دوسروں کو پلایا جاتا ہے پھر راجہ صاحب پیتے ہیں.اسی طرح ان کا کھانا ہے کہ ہزار احتیاطوں میں لگایا جاتا ہے.پھر اس سے پہلے خود اسی کو کھلایا جاتا ہے جو پکانے والا ہو.پھراس کو ڈاکٹر کھاتا ہے.پھر ان کے سامنے پیش ہوتا ہے.گویا ہر دم خطرہ ہے.اور احتیاط ہوتی رہتی ہے.ہر دم بے چینی رہتی ہے.مگر ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں.مگر کوئی خطرہ نہیں.اطمینان و سرور ہے.دشمن بھی اگر کھانے کی دعوت دیتا ہے تو بے دھڑک چلے جاتے ہیں.ایک دفعہ ایک یہودن عورت نے زہر بھی دے دیا مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کے الہام سے آپؐ کو یہ امر معلوم ہو گیا.اور آپؐ اس سے محفوظ رہے(سیرت النبی لابن ہشام زیر عنوان امر خیبر).آپؐ کو اس قدر اطمینان کیوں تھا؟ اسی وجہ سے کہ آپؐ نے ایک ایسی ہستی سے تعلق قائم کیا ہوا تھا جو غیب کو جانتی ہے اور اس سے جب کسی کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ اپنے غیب سے بندے کو بھی حسب ضرورت حصہ دیتا رہتا ہے.پس اس سے تعلق رکھنے والا مطمئن رہتا ہے.چونکہ مومن کسی کا حق نہیں مارتا اس لئے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے دینی ترقی میں اطمینان کی زیادتی اور دنیوی ترقی میں عدم اطمینان کی زیادتی کی ایک روحانی وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیوی ترقی جس قدر انسان کو
Page 73
حاصل ہوتی ہے اس کا مال زیادہ سے زیادہ مشتبہ ہوتا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کا حصہ اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوتا جاتا ہے.لیکن دینی ترقی کی یہ صورت نہیں.دینی ترقی میں انسا ن کس قدر بھی ترقی کرے وہ اپنا ہی حصہ لیتا ہے دوسروں کا حصہ نہیں مارتا.اسی کی طرف قرآن کریم میں دوسری جگہ اشارہ ہے کہ مومن کو جنت ملتی ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ عَرْضُہَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ( اٰل عمران :۱۳۴) یعنی جنت کی تمام لمبائی چوڑائی ہر مومن کو حاصل ہوگی.فرق صرف یہ ہوگا کہ ہر مومن بقدر ذوق و استعداد اس سے فائدہ حاصل کررہا ہوگا.پس روحانی ترقی میں کسی کا حق مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور چونکہ مومن کسی کا حق نہیں مارتا اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کی روح پر گناہ اور حق تلفی کا بوجھ نہیں ہوتا.اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَ حُسْنُ جو (لوگ) ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں ان کے لئے (بڑی) قابل رشک حالت اور بہترین مَاٰبٍ۰۰۳۰ واپسی کی جگہ( مقدر) ہے.حلّ لُغَات.طُوْبٰی مَصْدَ رٌبِمَعْنَی الطَّیِّبُ.طُوْبٰی مصدر ہے جو طیب کے معنے دیتا ہے.اصلہٗ طُیْبٰی قُلِبَتِ الْیَاءُ وَاوًا لِسُکُوْنِہَا بَعْدَ ضَمَّۃٍ.عربی کے قاعدہ کے مطابق یاواؤ سے تبدیل ہو گئی.نیز طَیِّبَۃٌ کی جمع ہے اور اَطْیَبَ کی تانیث ہے.اور اس کے معنے ہیں اَلْغِبْطَۃُ رشک.اَلسَّعَادَۃُ.نیک بختی.اَلْحُسْنٰی.اچھا انجام.اَلْخَیْرُ.بھلائی.(اقرب) طُوْبٰی کی صفت محذوف ہے یعنی اَلْحَالَۃُ معنے یہ ہوں گے کہ قابلِ رشک حالت.اچھی حالت.اَلْمَاٰبُ.اَلْمَرْجِعُ.لوٹنے کی جگہ.اَلْمُنْقَلَبُ واپسی کی جگہ.(اقرب) تفسیر.یعنی مومن کو نیکی اور سعادت حاصل ہوگی اور ایسے انعامات ملیں گے جن سے بڑھ کر ذہن میں نہیں آسکتے اور آخری ٹھکانا نہایت اعلیٰ ہوگا اور اچھا وہی ہے جس کا انجام اچھا ہو.
Page 74
َذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْۤ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَاۤ اُمَمٌ اسی لئے ہم نے تجھے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے کئی قومیں (آنے والے کی راہ دیکھتی) گزر چکی تھیں بھیجا ہے لِّتَتْلُوَاۡ عَلَيْهِمُ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُوْنَ تاکہ جو(کلام) ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے تو وہ انہیں اس حالت میں پڑھ کر سنائے کہ وہ رحمان (کے فیضان) کا بِالرَّحْمٰنِ١ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ١ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ انکار کر رہےہیں.تو کہہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اورا سی کی طرف اِلَيْهِ مَتَابِ۰۰۳۱ (ہرآن) میرا رجوع ہے.حلّ لُغَات.مَتَابَ.تَابَ کا مصدر ہے اور تَابَ اِلَی اللہِ مِنْ ذَنْبِہٖ کے معنے ہیں رَجَعَ عَنِ الْمَعْصِیَّۃِ گناہ سے لوٹا.اور مَتَاب کے معنے ہوئے گناہ سے لوٹ کر آنا.(اقرب) مَتَابِ.اصل میں مَتَابِیْ تھا یاء کو حذف کر دیا گیا اور باء کے کسرہ پر اکتفا کیا گیا.تفسیر.کیا لطیف بات بیان فرمائی کہ یہ عذاب مانگ رہے ہیں مگر باوجود اس کے ہم اپنی رحمانیت کے ماتحت عذاب میں تاخیر ڈال رہے ہیں.پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان نہیں ہے.اگر ہم رحمان نہ ہوتے تو تم کب کے تباہ ہوچکے ہوتے.تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم بچے ہوئے ہو.آخر ہماری رحمانیت ہی تو تمہاری حفاظت کررہی ہے.كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ سے یہ بتایا ہے کہ جس قسم کے مطمئن دل والے اور اچھے انجام کا ذکر ہم نے کیا ہے تیری بعثت اسی غرض سے ہے کہ ایسے اعلیٰ روحانی اور اخلاقی مقام والے لوگ تیرے ذریعہ سے بھی پیدا ہوں.قُلْ هُوَ رَبِّيْ اَلْآیہ.میں اس طرف اشارہ ہے کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ تم عرب جیسی سخت دل قوم کو کہاں اس قسم کا بنا سکو گے.مگر تم کہنا کہ یہ میرا کام تو نہیں خدا تعالیٰ کا کام ہے.میں اس پر توکل کروں گا اور بار بار اس کی طرف جھکوں گا تو یہ مقصد پورا ہو جائے گا.
Page 75
قوموں کی اصلاح کا ذریعہ توکل اور دعا ہے.پس قومی اصلاح کا اصل ذریعہ توکل اور دعا ہے.جو لوگ ظاہری اسباب سے دلوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے.ظاہری اسباب سے ظاہر ہی درست ہو سکتا ہے دلوں میں ایمان اور اطمینان نہیں بھرا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ یورپ باوجود پوری سعی کے اخلاقی ترقی میں کوئی اعلیٰ معیار پیش نہیں کر سکا جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود سامان نہ میسرآنے کے صحابہ کے ذریعہ سے پیش کیا.وَ لَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہو جس کے ذریعہ سے( نشان کے طور پر) پہاڑوں کو( ان کی جگہ سے ہٹا کر) چلایا گیاہو یا اس الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ١ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا١ؕ کےذریعہ سے زمین کو( ٹکڑے) ٹکڑے کیا گیا ہو یا اس کےذریعہ سےمردوں سے باتیں کی گئی ہو ں( تو کیا یہ لوگ اس اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى پرایمان لے آئیں گے؟) نہیں بلکہ( ایمان لانے کا) معاملہ پورے طور پر اللہ کے اختیار میں ہے پھر کیا جو (لوگ) النَّاسَ جَمِيْعًا١ؕ وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا ایمان لائےہیں انہیں (اب تک) معلوم نہیں ہوا کہ اگر اللہ( تعالیٰ) چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ ( اے رسول) جن لوگوں نے(تمہارا) انکار کیا ہے ان کے (اس) عمل کی وجہ سے ہمیشہ کوئی (نہ کوئی) سخت آفت
Page 76
وَعْدُ اللّٰهِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَؒ۰۰۳۲ ان پر آتی یا ان کے گھر کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ( تعالیٰ) کا (آخری) وعدہ آجائے گا.اللہ (تعالیٰ) اس وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا.حلّ لُغَات.سُیِّرَتْ.سَیَّرَہٗ کے معنے ہیں جَعَلَہٗ سَائِرًا.اس کو چلایا.سَیَّـرَالجُلَّ عَنْ ظَھْرِالدَّابَّۃِ.اَلْقَاہُ.سواری کا پالان اتار کر زمین پر رکھ دیا.اَلْمَثَلَ.جَعَلَہٗ یَسِیْرُ بَیْنَ النَّاسِ کسی مثال کو لوگوں میں مشہور کیا.مِنْ بَلَدِہٖ.اَخْرَجَہٗ وَأَجْلَاہٗ.کسی کوشہر بدر کیا.اور جلاوطن کیا.اَلْجِبَالُ.اَلْجَبَلُ کی جمع ہے اور اَلْجَبَلُ کے معنے ہیں کُلُّ وَتَدٍ لِلْأَرْضِ عَظُمَ وَطَالَ.زمین پر اونچے ٹیلے کو جبل کہتے ہیں.خِلَافُ السَّاحِلِ پتھریلی زمین.سَیِّدُ الْقَوْمِ وَعَالِمُھُمْ.قوم کا سردار اور عالم.یُقَالُ فُلَانٌ جَبَلُ قَوْمِہٖ.چنانچہ محاورہ ہے فلاں شخص اپنی قوم کا جبل ہے.یعنی سردار ہے یا قوم میں عالم کی حیثیت رکھتا ہے.(اقرب) پس سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ کے معنی ہوں گے کہ اس کے ذریعے سے پہا ڑاپنی جگہ سے ہلا دیئے جائیں.یعنی زلزلے آئیں.(۲) سردار یا عالم اڑا دیئے جائیں.(۳)بادشاہتوں کو اڑا دیا جائے.جَبَل کا لفظ روحانیت میں مشکلات پر بھی دلالت کرتا ہے.اس لحاظ سے معنے ہوں گے کہ مشکلات کو دور کیا جاوے.قُطِّعَتْ.قَطَعَ کے معنی ہیں کاٹا.اور قَطَّعَ.قَطَعَ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.فرق صرف یہ ہے کہ قَطَّعَ میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور قَطَّعَ اللہُ عَلَیْہِ الْعَذَابَ کے معنے ہیں لَوَّنَہٗ وَجَزَّأَہٗ.کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قسم قسم کے عذاب نازل کئے.یہاں تک کہ اس کے بال سفید ہو گئے.اور جتھا ٹوٹ گیا.(اقرب) قَطْعُ الْاَرْضِ یعنے زمین کاٹنے سے مراد یا تو یہ ہے کہ دشمنوں کا علاقہ کاٹ کر مسلمانوں کو دیا جاوے گا یا یہ تعلیم فوراً زمین کو طے کرتی ہوئی پھیل جائے گی.یَایْئَسْ.یَئِسُ سے فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے اور یَئِسَ کے معنے ہیں قَنَطَ.ناامید ہو گیا.عَلِمَ جان لیا.(اقرب) آیت اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا میں یایئس کے معنے جاننے کے ہیں.یعنی کیا انہیں معلوم نہیں ہوا.أَلْقَارِعَۃُ أَ لْقَارِعَۃُ کے معنے ہیں اَلدَّاھِیَۃُ بلائے ناگہانی، صدمہ.اَلْقِیَامَۃُ.قیامت.یُقَالُ قَرَعَتْھُمْ قَوَارِعُ الدَّ ھرِ أَیْ اَصَابَتْھُمْ نَوَازِلُہُ الشَّدِیْدَۃُ اور جب قَرَعَتْھُمْ قَوَارِعُ الدَّ ھْرِ کا محاورہ بولیں
Page 77
تو یہ معنی مراد ہوتے ہیں کہ ان کو سخت تکالیف پہنچیں.اَلنَّکْبَۃُ المُہْلِکَۃُ ہلاک کر دینے والی مصیبت.سَریَّۃُ النَّبِیِّ الْمُسْلِمِیْنَ آنحضرتؐ کے چھوٹے لشکر کو بھی قَارِعَہ کہتے تھے.قَارِعَۃُ الطَّرِیْقِ.وَمُعْظَمُہُ وَاَعْلَاہُ.راستے کے اونچے بڑے حصہ کو بھی قَارِعَہ کہتے ہیں.حَلَّ حَلَّ الْمَکَانَ اور حَلَّ بِہٖ کے معنے ہیں نَزَلَ بِہٖ کسی جگہ اترا.بِہٖ فِی الْمَکَانِ.اَحَلَّہٗ اِیَّاہُ.اس کو کسی جگہ اتارا.اَلرَّجُلُ.عَدَا.زیادتی کی.(اقرب) تفسیر.یعنی اگر کوئی ان صفات والا قرآن ہو جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں.یہ مراد نہیں کہ قرآن میں یہ صفات نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن کریم سے یہ صفات ظاہر ہوں گی مگر پھر بھی یہ لوگ فائدہ نہ اٹھائیں گے.جیسے حدیث میں ہے لَوْکَانَ الْاِیْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَیَّا لَنَالَہٗ رَجُلٌ مِّنْ فَارِس (بخاری کتاب التفسیر تفسیرسورة الجمعة).اس سے یہ مراد نہیں کہ نہ ایمان ثریا پر چلا گیا ہے اور نہ رجل فارس اسے واپس لائے گا.بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایمان ایک دن ثریا سے معلق ہو جائے گا اور رجل فارس اسے واپس لائے گا.پس اس جگہ کفار کی سنگدلی ظاہر کرنی مقصود ہے.جو صفات اس جگہ قرآن کریم کی بتائی ہیں وہ یہ ہیں.(۱)سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ.اس کے ذریعہ سے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے.ظاہری معنے لئے جاویں تو مراد یہ ہوگی کہ اس میں شدید زلازل کی خبر دی گئی ہو جن سے پہاڑوں کی چوٹیاں اپنی جگہوں سے ہل جائیں.قرآن کریم میں ایسی زبردست پیشگوئیاں مادی تغیرات کی موجود ہیں جیسا کہ سورئہ زلزال میں.اور اگر استعارہ مراد لیا جائے تو معنے یہ ہوں کہ بڑی بڑی مشکلات دور کر دی جائیں.کیونکہ پہاڑ استعارۃً مصیبت اور مشکل کو بھی کہتے ہیں.یہ صفت بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ علمی، اخلاقی، روحانی، تمدنی، اقتصادی سیاسی قومی مشکلات کا حل قرآن کریم نے ایسا کیا ہے کہ کوئی دوسری کتاب اس میں اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی.اور اگر جبل کے دوسرے معنے لئے جائیں جو سردارِ قوم یا عالم کے ہیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن کے ذریعہ سے پرانے سردار بھی اڑ گئے اور پرانے عالم بھی.اس نے سیادت کا بھی رنگ بدل دیا.بادشاہت کی جگہ خلافت کو قائم کیا.اور علم کا پرانا مفہوم جو وہم اور تخمین پر مبنی تھا اس کی جگہ تجربہ مشاہدہ اور خواص اشیاء پر علم کی بنیاد رکھی.تمام قرآن کریم اس مضمون سے پر ہے کہ وہم کی جگہ فکر اور عقل سے کام لو اور سیاروں پہاڑوں، دریاؤں، شہروں موسمی تغیرات اور خواص اشیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور مشاہدہ سے اس کی حقیقت دریافت کرو.کہ یہ سب کچھ تمہارے فائدہ اور خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے.پس قرآن کریم نے پرانی سیاست اور پرانے علم
Page 78
کو بالکل بدل دیا اور دونوں امور کے متعلق نیا نقطۂ نگاہ دنیا کے سامنے پیش کرکے گویا ایک نئی دنیا بسادی.قطع ارض کے معنے (۲) دوسری صفت قطع ارض بتائی.قطع ارض کے معنے مسافت کے چھوٹا ہوجانے کے بھی ہوسکتے ہیں.یعنی وہ کتاب سب زمین میں آسانی سے پھیل جائے اور یہ بھی کہ زمین اس کے ذریعہ سے کاٹ لی جائے.یعنی اس کی پیشگوئیوں کے مطابق دشمنوں کا علاقہ کاٹ کر مسلمانوں کو دے دیا جائے.یہ دونوں باتیں بھی قرآن کریم کو حاصل ہوئیں.یعنی آناً فاناً وہ دنیا میں پھیل بھی گیا اور اس نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ایسا جوش پیدا کر دیا کہ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر سب دنیا میں پھیل گئے اور ایک نسل کے اندر ساری دنیا پر اس کے ماننے والے چھا گئے اور یہ بھی ہوا کہ اس کی برکت سے اور اس کی پیشگوئیوں کے مطابق اس کے مخالفوں کے ملک کاٹ کاٹ کر مسلمانوں کی املاک میں شامل کر دیئے گئے.مردوں کے بلوائے جانے سے مراد روحانی مردوں کا زندہ ہو کر بولنا ہے (۳) تیسری صفت یہ بتائی کہ اس کے ذریعہ سے مردوں کو بلوایا جائے.اس کے بھی کئی معنے ہوسکتے ہیں.مثلاً یہ کہ اس کی شہادت میں مردے بولنے لگ جائیں.چونکہ مردوں کا اس دنیا میں زندہ ہونا قرآن تعلیم کے خلاف ہے اس لئے ان معنوں کو مدنظر رکھ کر اس کے یہ معنے ہوں گے کہ مردے خواب میں آکر بولیں یا کشف میں بولیں.سپر چولزم کی طرف میلان تجربہ شاہد ہے کہ لوگ اپنے آباء کی شہادت کو بہت مانتے ہیں.اس زمانہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کئی لوگ دلائل سے مان لیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلعم کی زیارت ہو اور وہ کہہ دیں تو ہم مان لیں گے.یورپ میں اس وقت سپرچولزم کی طرف شدید میلان بھی اسی خواہش کی وجہ سے ہے.پس اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے آباء سے شدید تعلق رکھتے ہیں اور بظاہر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے وفات یافتہ آباء کہہ دیں تو ہم مان لیں گے لیکن جب آباء کی شہادتیں تورات انجیل سے پیش کی جائیں تو پھر انکار کر دیتے ہیں.یا حضرت ابراہیم کی شہادت مکہ والوں کو پیش کی جائے تو بھی منکر ہی رہتے ہیں.یا پھر لوگوں کو خوابوں اور کشوف میں ان کے آباء آکر قرآن کریم کی صداقت پر گواہی دیں تب بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں.اس زمانہ میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ تو رؤیا پر ایمان لاتے ہیں کئی لوگوں کو رسول کریم صلعم یا دوسرے بزرگ بھی رؤیا میں نظر آکر مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی شہادت دے جاتے ہیں.مگر لوگ نہیں مانتے.میں نے دیکھا ہے کہ ہزارہا آدمیوں کو رؤیا اور کشوف میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی وفات یافتہ بزرگوں کی زبانی بتائی گئی ہے.
Page 79
معلوم ہوتا ہے یہی سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھا مگر آج کل کی طرح اس زمانہ میں بھی کئی لوگ ان رؤیا اور کشوف سے فائدہ نہ اٹھاتے تھے.مردوں کے بلوائے جانے سے دوسرے معنے یہ ہوسکتے ہیں کہ جو لوگ روحانی مردے تھے قرآن کریم کے ذریعہ سے انہیں بلوا دیا جائے گا.یعنی وہ صرف زندہ ہی نہ ہو جائیں گے بلکہ بولنے بھی لگیں گے.یعنی اعلیٰ علوم ان کی زبان پر جاری ہوجائیں گے.اور وہ دنیا کے لئے ہادی ہو جائیں گے.قرآن کریم میں متواتر روحانیت سے محروم لوگوں کو مردہ کہا گیا ہے اور ان کے روحانیت حاصل کرنے کو زندگی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے.مثلاً فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ (الانفال:۲۵) اے مومنو! جب خدا اور اس کا رسول تم کو زندہ کرنے کے لئے بلایا کریں تو ان کی آواز کو قبول کیا کرو.پس معلوم ہوا قرآنی اصطلاح کی رو سے روحانیت سے بُعد موت اور اس کا حصول زندگی کہلاتا ہے.ان معنوں کی رو سے مردوں کے بلوا دینے کے معنے روحانیت سے دور لوگوں کا اسلام لانا اور روحانیت میں ترقی کرکے دنیا کے لئے ہادی ہو جانا لئے جائیں گے.چنانچہ اس کی مثالیں بکثرت شروع اسلام میں پائی جاتی ہیں.اسلام کے اشد ترین دشمنوں کا اسلام لانا حضرت عمرؓ جیسے اشد مخالف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے گھر سے نکلے تھے اسلام لاکر انہوں نے کس قدر اسلام کے لئے قربانی کی اور اسلام کی اشاعت میں کس قدر حصہ لیا.ایسا ہی خالد ؓبن ولید جو بڑے مخالف اور دشمن تھے بعد میں مسلمان ہو کر اسلام کے لئے ایک نہایت مفید وجود ثابت ہوئے.ایسا ہی عکرمہ جو ابوجہل کے لڑکے تھے اور اسلام کے خطرناک مخالف تھے آخر اسلام لائے اور اشاعت اسلام میں جان تک کی پرواہ نہ کی.بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا.سب امور خدا تعالیٰ کے ہی قبضہ میں ہیں.یعنی مذکورہ بالاامور بظاہر ناممکن معلوم ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ لو گے کہ کس طرح یہ نشان قرآن کریم کی تائید میں ظاہر ہوتے ہیں.اس آیت میں یَایْئَسُ کے معنی یَعْلَمُ کے ہیں اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ.جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے یَایِئَسُ کے معنے اس جگہ یَعْلَمُ کے ہیں.یعنی کیا کفار کو یہ معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ سب کو ہدایت دے.اور آگے اس ہدایت کا وقت بتایا کہ اس قوم پر عذاب پر عذاب آئیں گے اور لشکر کے بعد لشکر چڑھائی کرے گا.(قارعہ سے مراد لشکر ہے) اور آخری لشکر ان کے گھروں کے پاس جاکر اترے گا.یعنی مکہ پر حملہ ہوگا تب وہ اوپر کا وعدہ پورا ہوگا.یعنی یہ وعدہ کہ خدا چاہے تو سب کو ہدایت دے دے.چنانچہ ایسا ہی ہوا.متواتر اسلام
Page 81
گمراہی میں مہلت دی.الْبَعیْرَ وَسَّعَ لَہٗ فِی قَیْدِہِ اونٹ کی رسی کو لمبا کیا.وَعِبَارَۃُ الْأَسَاسِ’’ اَمْلَیْتُ الْقَیْدَ لِلْبَعِیْرِ! اَرْخَیْتُہُ وَاَوْسَعْتُہُ‘‘ اور اساس میں اَمْلَیْتُ الْقَیْدَ لِلْبَعِیْرِ کے معنے یوں کئے گئے ہیں کہ میں نے اونٹ کے باندھنے کی رسی کو لمبا اور ڈھیلا کر دیا.اللہُ الظَّالِمَ.اَمْھَلَہٗ اللہ نے ظالم کو مہلت دی.(اقرب) پس اَمْلَیْتُ کے معنے ہوں گے میں نے مہلت دی.ڈھیل دی.اَخَذَہٗ اللہُ اَھْلَکَہُ.اللہ نے اسے ہلاک کیا.فُلَانًا بِذَنْبِہِ.عَاقَبَہٗ عَلَیْہِ.کسی کے گناہ پر اسے سزا دی.(اقرب) اور اَخَذْتُھُمْ کے معنے ہوں گے (۱) میں نے ان کو ہلاک کر دیا.(۲) میں نے ان کو گناہوں پر سزا دی.تفسیر.منکرین کو ڈھیل دی جانی ضروری ہوتی ہے چونکہ کفار باربار اعتراض کرتے تھے کہ عذاب فوراً کیوں نہیں آتا؟ا ور ان کو جواب دیا گیا تھا کہ ہماری غرض ہدایت ہے.اس لئے ڈھیل کادیا جانا ضروری ہے.پہلے انبیاء کے منکرین کو ڈھیل دی گئی اب فرمایا کہ یہ ڈھیل کا دینا تیرے زمانہ کے منکروں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں کہ اعتراض ہو بلکہ سب رسولوں کے زمانہ میں ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ منکرین کو ڈھیل ملتی رہی.اور فوراً نہیں پکڑے گئے.پس اگر کسی مدعی کے منکروں کو ڈھیل کا ملنا ا سکے جھوٹ کی علامت ہے تو پھر پہلے نبیوں کو بھی نعوذباللہ جھوٹا ماننا پڑے گا.مکہ والے کم از کم حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمٰعیلؑ کو تو ضرور سچا مانتے تھے اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو بے انتہا تکالیف دی گئیں حتیٰ کہ آگ میں ڈالا گیا.مگر خداوند تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو فوراً نہ پکڑا بلکہ لمبی ڈھیل کے بعد پکڑا.آیت کے آخر میں اس امر کو بھی پیش کیا ہے کہ اصل میں دیکھنے والی بات یہ نہیں کہ ڈھیل کیوں مل رہی ہے.بلکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ منکرین جب پکڑے گئے تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا کیا ان کا انجام نہایت عبرتناک نہیں ہوا؟ پھر ڈھیل پر کیا اعتراض ہے؟ ڈھیل پر اعتراض تو تب ہو جب اس کا نتیجہ انبیاء کے حق میں مضر ہو.درمیانی ڈھیل تو بعثت انبیاء کی غرض یعنی خلق اللہ کی ہدایت کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے.اَفَمَنْ هُوَ قَآىِٕمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ١ۚ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ توکیا وہ( خدائے برتر )جو ہر ایک شخص کا جو کچھ اس نے کمایا ہو اس کے مطابق نگران ہے (ان سے نہ پوچھے گا) اور شُرَكَآءَ١ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ١ؕ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ۠ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي انہوںنے (تو) اللہ کے کئی ایک شریک (بھی) بنائے( ہوئے) ہیں (ان سے) کہو تم ان( نئے خداؤں) کے
Page 82
الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ١ؕ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ نام (تو) بتاؤ یا (کیا) تم (لوگ) اس (یعنی خدا تعالیٰ) کو کوئی ایسی بات بتاؤ گے جو زمین پر (موجود) تو ہے لیکن وہ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ١ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ (اسے) نہیں جانتا یا کوئی اور کھلی بات (کہو گے ؟مگر) نہیں(تم کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتے) بلکہ جن لوگوں نے انکار اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ۰۰۳۴ کیا ہے ان کو ان کی (اپنی ہی) فریب کاری خوبصورت (شکل میں )دکھائی گئی ہے.اور انہیں( درست) راستہ سے ہٹا دیا گیا ہے اور جسے اللہ ہلاک کرے پھر اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں( مل سکتا).حلّ لُغَات.قَائِمٌ قَامَ سے اسم فاعل ہے.اور قَامَ عَلَیْہِ کے معنےہیں رَاقَبَہٗ اس پر نگہبان رہا.عَلَی غَرِیْمِہِ.طَالَبَہٗ.(اقرب) اپنے قرضدار سے قرض کا مطالبہ کیا.اَفَمَنْ ھُوَقَائِمٌ عَلَی کُلِّ نَفْسٍ اَیْ حَافِظٌ لَّہَا (مفردات) یعنی اَفَمَنْ ھُوَ قَائِمٌ میں قَائِمٌ کے معنے محافظ و نگران کے ہیں.اَفَمَنْ ھُوَ قَائِمٌ کے آگے یہ جملہ محذوف ہے.کَمَنْ ھُوَ لَیْسَ بِقَائِمٍ.اور معنے یہ ہوں گے کہ کیا وہ ذات جونگہبان ہے اس جیسی ہوسکتی ہے جو نگہبان نہیں.تُنَبِّئُوْنَ.نَبَأَ سے ہے اور نَبَّأَہُ الْخَبَرَ وَبِالْخَبَرِ کے معنے ہیں خَبَّرَہٗ.اس کو خبر دی.یُقَالُ نَبَّأْتُ زَیْدًا عَمْرًوا مُنْطَلِقًا.أَیْ اَعْلَمْتُہٗ میں نے زید کو بتایا کہ عمرو جارہا ہے (اقرب) پس اَمْ تُنَبِّئُوْنَہٗ کے معنے ہوئے کیا تم اسے بتاؤ گے.تفسیر.اَفَمَنْ هُوَ قَآىِٕمٌکا جواب محذوف ہے اس آیت میںاَفَمَنْ هُوَ قَآىِٕمٌ کے جواب کا جملہ یعنی کَمَنْ ھُوَ لَیْسَ بِقَائِمٍ محذوف ہے اور یہ عربی زبان کا عام قاعدہ ہے کہ مقابل کا فقرہ لفظاً چھوڑ دیا جاتا ہے اور معناً اسے مدنظر رکھ لیا جاتا ہے.مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو انسانی اعمال میں سے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع نہیں جانے دیتی اور سب کے نتائج پیدا کرتی ہے اور جس کے ہاتھ سے کوئی بچ نہیں سکتا اس جیسی ہوسکتی ہے جس میں یہ طاقت نہیں؟ قَائِمٌ عَلٰی کُلِّ نَفْسٍ کے معنے ہیں کہ نگران کے طور پر سر پر کھڑا ہے.کوئی اس سے دور نہیں اور
Page 83
اس کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتا.پس اسے سزا میں جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سزا میں جلدی تو وہ کرتا ہے جس میں طاقت نہیں ہوتی اور جو اپنے مخالف کو پکڑ لینے پر ڈرتا ہے کہ میں نے فوراً سزا نہ دی تو شاید ہاتھ سے نکل جائے اور پھر میں اس پر قدرت نہ پاؤں.جب اللہ تعالیٰ ہر وقت قادر ہے اور پوری طرح قادر ہے تو وہ کمزوروں کی طرح جلدی کیوں کرے؟ پس ان کو سزا کی تاخیر پر ہنسنے یا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں.انہیں تو اس امر کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ خدا تعالیٰ کے مجرم ہیں یا نہیں؟ اگر خدا تعالیٰ کے مجرم ہیں تو پھر بے فکری اور خوشی کی کوئی وجہ نہیں.وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَسے بتایا کہ اگر یہ اپنے عقائد اور اعمال پر غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گاکہ یہ لوگ اس ذات کے مجرم ہیں جو سب کام خود کررہی ہے اور کسی کی امداد کی محتاج نہیں.لیکن یہ اس کے شریک مقرر کررہے ہیں.پس جب یہ اپنی ذات میں سزا کے مستحق ہوچکے ہیں تو یہ خیال ہی کس طرح کرسکتے ہیںکہ انہیں سزا نہیں ملے گی؟ قُلْ سَمُّوْهُمْ.قرآن مجید کا قاعدہ ہے کہ جب کسی اہم مسئلہ کا ذکر ضمنی طور پر بھی ہو تو وہ اس کی تفاصیل پر روشنی ڈال دیتا ہے.اس جگہ پر جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ دراصل اَفَمَنْ هُوَ قَآىِٕمٌ کے مضمون کی تشریح کے طور پر لایا گیا تھا لیکن چونکہ شرک کا ذکر آگیا اس لئے اس عقیدہ کی بے ہودگی ثابت کرنی ضروری سمجھی.چنانچہ شرک کے رد میں فرمایاقُلْ سَمُّوْهُمْ اگر شرکاء ہیں تو ذرا ان کے کام تو بتاؤ.سَمُّوْھُمْ سے یہ مراد نہیں کہ نام بتاؤ کیونکہ نام تو بتوں کے انہوں نے رکھے ہی ہوئے تھے.خود قرآن کریم نے بھی کئی نام گنائے ہیں.پس مراد اسماء ذات نہیں بلکہ صفاتی نام ہیں.ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنْ هِيَ اِلَّاۤ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَاۤ (النجم :۲۴) یہ بت جن کو تم معبود قرار دیتے ہو نام ہی نام ہیں اور ہے کیا ؟یعنی ان میں کوئی صفات تو ہیں نہیں.آیت زیرتفسیر میں بھی یہی مراد ہے کہ ان شرکاء کے ذرا کام تو بتاؤ.شرک کے خلاف ایک زبردست دلیل یہ ایسی زبردست دلیل ہے جس کا کوئی مشرک جواب نہیں دے سکتا.کیونکہ اگر وہ یہ کہے کہ مثلاً اس بت کا کام بیٹا دینا ہے تو اس میں سب صفات الٰہی ماننی پڑیںگی.کیونکہ بیٹا دینے کے لئے ایک طرف تو رحم کی اصلاح کی ضرورت ہوگی اور دوسری طرف اگر مادہ تولید میں نقص ہے تو مرد کی اس مرض کو دور کرنا ہوگا.اور اس کے لئے غذاؤں اور دواؤں اور ان کے اثرات پر تصرف ضروری ہے.اور جب ایک بت کو یہ بات حاصل ہوگی تو پھر ماننا پڑے گا کہ غذاؤں پر بھی اسے تصرف حاصل ہے اور انسانی مشین کاچلانے والا دواؤں کے اثرات کو قبضہ میں رکھنے والا بھی وہی بت ہے نہ کہ خدا.اور دواؤں کا اثر اجرام فلکیہ کے اثر کے تابع ہے.اس لئے اس کا تصرف اجرام فلکیہ پر بھی تسلیم کرنا ہوگا.ایسا ہی پھر اس کے لئے یہ بھی ضروری ہوگا کہ اسے علم غیب ہو.
Page 84
ورنہ وہ کیسے جانے گا کہ مریض کے موجودہ حالات میں اس کے لئے فلاں دوا ہی مفید ہے اور پھر اسے صرف عالم الغیب ہی نہیں بلکہ معلم بھی ہونا چاہیے تا وہ حکیم کے ذہن میں یا اس کی بیوی یا خود اس مریض کے ذہن میں یہ بات پیدا کرے کہ اس کو یہ چیز کھلاؤ یا تم کو یہ چیز کھانی چاہیے.جس سے مادہ تولید درست ہوگا.وغیرہ.غرض جب تک تمام صفات نہ ہوں گی صرف کوئی ایک صفت کام نہ کرسکے گی.اور اگر باقی تمام صفات بھی اس میں مان لی جائیں تو پھر خدا جیسا ایک دوسرا خدا ماننا پڑے گا.اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ دنیا کا کارخانہ ہزاروں خدا جن میں سے ہر اک آزاد طور پر اس کارخانہ کو چلاسکتا ہے مل کر چلار ہے ہیں اور یہ ایسا فضول کام ہے کہ معبود تو الگ رہا عام انسان کے بارہ میں بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا.ایک پادری سے الوہیت مسیح کے متعلق سوال میں نے ایک مرتبہ ایک عیسائی سے پوچھا کہ دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مسیح ؑ نے میں نے کہا کیا خدا میں بھی طاقت ہے کہ دنیا کو پیدا کرسکے؟ اس نے کہا ہاں.میں نے کہا پھر کیا وہ معطل اور بے کار بیٹھا ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ بھی پیدا کررہا ہے اور پھر یہی بات روح القدس کے متعلق کہی.تب میں نے ان سے کہا کہ آپ کے سامنے آپ کی میز پر ایک پنسل پڑی ہے اگر آپ اپنے نوکر سے کہیں کہ یہ پنسل مجھے اٹھا دو اور وہ جاکر دواور آدمیوں کو بھی بلا لائے اور پھر تینوں مل کر اس پنسل کو اٹھا کر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں تو آپ ان کو کیا سمجھیں گے؟ اس نے کہا پاگل.میں نے کہا جب ہر ایک خدا الگ الگ دنیا کو پیدا کرسکتا تھا تو پھر یہ تین مل کر اس کام کو کیوں کررہے ہیں.جسے ایک ہی کرسکتا تھا گھبرا کر بولا اصل میں تثلیث کا مسئلہ ایسا باریک ہے کہ انسان کی عقل میں نہیں آسکتا.یہ سَمُّوْھُمْ والی دلیل ہی تھی کہ جسے میں نے استعمال کیا اور پادری بالکل حیران رہ گیا.عربی محاورہ کے رو سے سَمُّوْھُمْ کے دوسرے معنے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ ان کی حقیقت ہی کیا ہے.عربی میں حقارت کے لئے کہتے ہیں.سَمِّہٖ.اس کا نام تو لو.مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی ذلیل چیز ہے کہ اس کا نام لیتے ہی تم شرمندہ ہو جاؤ گے.ہوسکتا ہے کہ یہاں بھی ان معنوں میںسَمُّوْھُمْ کہا گیا ہو.مطلب یہ کہ ذرا نام تو لو.نام لیتے ہی خود ہی شرمندہ ہو جاؤ گے.اردو میں نام لینے کی بجائے کہتے ہیں ’’منہ تو دکھا.‘‘ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ۠میں شرک کے خلاف دوسری دلیل اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ۠ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ.شرک کے خلاف دوسری دلیل یہ دی ہے کہ اگر کوئی خدا کا شریک ہوتا تو اس کی خبر خدا کی طرف سے آنی چاہیے تھی.جیسا کہ ڈپٹی کمشنر گورنمنٹ مقرر کرتی ہے تو وہی اعلان کرتی ہے نہ یہ کہ ضلع کے لوگ.یعنی اگر خدا نے ان
Page 85
کو اپنا شریک بنایا تھا تو ان کے لئے کوئی نبی آتا اور اعلان کرتا کہ یہ خدا کے شریک ہیں یا فرشتے اترتے اور وہ اعلان کرتے.مطلب یہ کہ بالواسطہ اعلان ہوتا یا بلاواسطہ اور یا پھر کم از کم وہ شریک خود ہی یہ اعلان کرتے کہ ہمیں خدا نے اپنا شریک مقرر کیا ہے.مگر یہاں تو ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں.اس لئے فرمایا کہ کیا تم اللہ کو اطلاع دیتے ہو جس بات کا اسے زمین میں علم نہیں؟ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِکے دو معنی اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ اس کے دو معنے ہیں.(۱)اَمْ تَقُوْلُوْنَ بِظَاہِرٍ مِنَ الْقَوْلِ.یعنی یہ بات تم صرف زبان سے کہتے ہو.دل میں اس کے منکر ہو.دل میں اس کی عظمت نہیں.کیونکہ دل میں کسی چیز کی عظمت دلیل سے پیدا ہوا کرتی ہے.معنے یہ ہوئے کہ جو کچھ کہہ رہے ہو کیا خود تمہارے دل اس کو مانتے ہیں؟ اس طرح فطرت سلیمہ سے اپیل کی جو بسا اوقات نہایت کامیاب طریقہ صداقت کی طرف لانے کا ہوتا ہے.دوسرے معنے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ اس کی کوئی نقلی دلیل بتاؤ.کیا کوئی خدا کا کلام یا اس کی وحی ہے جس کی بناء پر تم ایسا کہتے ہو؟ لیکن جب کوئی بھی صورت نہیں تو انہیں شریک قرار دینا کیونکر درست ہوسکتا ہے.سَمُّوْھُمْ کہہ کر یہ بتایا تھا کہ ان بتوں میں کوئی ذاتی کمال نہیں.اَمْ تُنَبِّئُوْنَہٗ میں عقلی دلیل اور الٰہی شہادت کی عدم موجودگی بیان فرمائی ہے اوربِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ میں نقلی دلیل کا بھی انکار کیا ہے اور فطرت کی شہادت کا بھی.بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ.جب انسا ن کوئی فریب کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکا دے کر ٹھگنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ خود اور اس کی اولاد بھی اس فریب کا شکار ہوجاتی ہے.زین کا محذوف فاعل خدا تعالیٰ نہیں بلکہ ان کے اپنے نفس ہیں.یعنی پہلے تو بعض لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لئے شرک کا ڈھکوسلا بناتے ہیں مگر آخر کار خود بھی انہیں وہ بات اچھی لگنے لگ جاتی ہے اور اولاد تو اس وہم کا بالکل ہی شکار ہوجاتی ہے.قرآن مجید اور کمپرٹیو ریلجن کے ماہرین کا اختلاف صُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ یعنی جب وہ خدا کے تعلق کو چھوڑتے ہیں تو شرک میں مبتلا ہوجاتے ہیں.انسان بغیر ساتھی کے نہیں رہ سکتا.خدا کو چھوڑنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا ڈھونڈنے لگتا ہے.اور اسی طرح شرک پیدا ہوجاتا ہے.بِئْسَ لِلظَّالِمِیْنَ بَدَلًا اس مسئلہ میں قرآن مجید اور کمپریٹوریلجن کے ماہرین کا اختلاف ہے.قرآن مجید کہتا ہے کہ پہلے توحید تھی بعد میں شرک پیدا ہوا مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے شرک تھا آہستہ آہستہ خدا کا خیال پیدا ہوا.اور توحید دنیا میں آئی (Encyclopedia of Religion and Ethics underword Polytheism).
Page 87
الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ١ؕ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ١ؕ اُكُلُهَا جس کا پرہیزگاروں کو وعدہ دیا گیا ہے.(یہ ہے کہ) اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس کاپھل دَآىِٕمٌ وَّ ظِلُّهَا١ؕ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا١ۖۗ وَّ عُقْبَى (بھی) ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور اس کا سایہ (بھی).یہ ان( لوگوں) کا انجام ہوگا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا (ہوگا) الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ۰۰۳۶ اور انکار کرنے والوں کا انجام (دوزخ کی )آگ ہے.حلّ لُغَات.اَشَقُّ.شَقَّ سے ہے اور شَقَّ کے معنے ہیں صَدَعَہٗ.اس کو پھاڑا.فَرَّقَہ ٹکڑے ٹکڑے کیا.عَلَیْہِ الْاَمْرَ شَقًّا.صَعُبَ.معاملہ مشکل ہو گیا.عَلٰی فُلَانٍ اَوْقَعَہٗ فِی الْمَشَقَّۃِ کسی کو مشقت میں ڈال دیا.(اقرب) اَشَقُّ کے معنے ہوئے بہت سخت.اَلْمَثَلُ.اَلشِّبْہُ.مشابہ.اَلنَّظِیْرُ.نظیر.اَلصِّفَۃُ.بیان.اَلْحُجَّۃُ.دلیل.یُقَالُ اَقَامَ لَہٗ مَثَلًا أَیْ حُـجّۃً اور اَقَامَ لَہٗ مَثَلًا میں مثلا دلیل کے معنی میں استعمال ہو اہے.اَلْحَدِیْثُ.عام بات.اَلْقَوْلُ السَّائِرُ.ضرب المثل.اَلْاٰیَۃُ.نشان.جَنَّۃٌ کے معنوں کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ ہٰذاآیت نمبر۲۴جلد ھٰذا.تفسیر.جیسا کہ حل لغات میں بیان ہوچکا ہے جنت اس زمین کو نہیں کہتے جس میں درخت ہوں بلکہ اصل میں سایہ کرنے والی چیز کو کہتے ہیں.پس تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ سے مراد یہ ہوئی کہ باغوں کے اندر درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی.گویا اس سے ایک تو پانی کے قرب کی طرف اشارہ کیا دوسرے اس طرف اشارہ کیا کہ وہ خود نہروں کے مالک ہوں گے.نھر سے وسعت عمل پر دلالت ہوتی ہے نھر.سہولت سے چلنے والے پانی کو کہتے ہیں.پس نھر سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہا ںانہیں بے روک ٹوک ترقیات حاصل ہوں گی.نیز نھر سے وسعتِ عمل پر بھی دلالت ہوتی ہے.کیونکہ دس بیس گھماؤ ںزمین کے لئے نہر نہیں جاری کی جاتی بلکہ وسیع رقبوں کے لئے جاری کی جاتی ہے.
Page 88
پس اس سے اشارہ کیا گیا ہے کہ مومن کے اعمال بہت وسیع ہوتے ہیں.وہ کنوئیں کے مینڈک کی طرح محدود نگاہ نہیں رکھتا.پھر جمع کا لفظ انہار بول کر یہ بھی بتا دیا کہ نھر کے لفظ سے جن فوائد کی طرف اشارہ ہے وہ کئی اقسام کے ہوں گے.نھر کا لفظ روحانی عالم میں عمل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے نَھر کا لفظ روحانی عالم میں عمل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے.پس بتایا ہے کہ جس طرح مومن کے عمل مختلف اور کئی اقسام کے ہوتے ہیں ویسے ہی روحانی عالم میں ان کا تمثل بھی کئی نہروں کی صورت میں ظاہر ہوگا.اور ہر قسم کے عمل کے مقابل پر ایک نہر جاری ہوگی اور ہر وقت مومن کو توجہ دلاتی رہے گی کہ یہ تمہارا فلاں عمل کام دے رہا ہے.اُكُلُهَا دَآىِٕمٌ وَّ ظِلُّهَا.ظِلُّہَا میں یہ بتایا ہے کہ وہاں خزاں کبھی نہ آئے گی پتے ہمیشہ رہیں گے.یعنی جنت کی راحتوں اور نعمتوں میں وقفہ نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ ہی رہیں گی.اکل سےباطن کو راحت ہوتی ہے اور ظِلّ سے ظاہر کو پھراُكُلُهَا دَآىِٕمٌ وَّ ظِلُّهَا میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ظاہری اور باطنی نعمتیں قائم رہیں گی.اکل سے باطن کو راحت ہوتی ہے اور ظل سے ظاہر کو.وَعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ.انہوں نے اپنی روحانی ترقیات کو مدنظر نہ رکھا بلکہ دوسروں کے پیچھے چل پڑے اور کہہ دیا کہ مَاوَجَدْنَا عَلَیْہِ اَبَاءَ نَا پر ہم قائم رہیں گے گویا ان کی زندگی اپنے لئے نہ رہی دوسروں کے لئے ہو گئی اس لئے فرمایا ہم بھی تمہیں آگ میں ڈالیں گے جو دوسروں کو فائدہ دیتی ہے اور خود جلتی ہے.وَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ اور جن( لوگوں) کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (کلام الٰہی) سے جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے خوش ہوتےہیں اور ان مِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ١ؕ قُلْ اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ (مختلف)گروہوں میں سے (بعض) ایسے( بھی) ہیں جو اس کے بعض (حصہ) کا انکار کرتے ہیں تم کہو مجھے (تو)
Page 89
اَعْبُدَ اللّٰهَ وَ لَاۤ اُشْرِكَ بِهٖ١ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَ اِلَيْهِ مَاٰبِ۰۰۳۷ یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور( کسی کو) اس کا شریک نہ ٹھہراؤں میں اسی کی طرف (تم کو) بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میں( بھی) رجوع کرتاہوں.حلّ لُغَات.اَلْاَحْزَابُ.اَلْحِزْبُ کی جمع ہے.اور اَلْحِزْبُ کے معنے ہیں.اَلطَّائِفَۃُ.گروہ.جَمَاعَۃُ الناسِ.لوگوں کی جماعت.جُنْدُ الرَّجُلِ وَاَصْحَابُہُ الَّذِیْنَ عَلَی رَأْیِہِ.ایسے دوست اور ساتھی جو ہم خیال اور ہم رائے ہوں.اَلنَّصِیْبُ.حصہ.کُلُّ قَوْمٍ تَشَاکَلَتْ قُلُوْبُھُمْ وَاَعْمَالُھُمْ فَھُمْ اَحْزَابٌ وَاِنْ لَمْ یَلْقَ بَعْضُہُمْ بَعْضًا.تمام وہ لوگ جن کے اعمال اور دل آپس میں مشابہ ہوں.اگرچہ وہ آپس میں ملے نہ ہوں.احزاب کہلاتے ہیں.(اقرب) تفسیر.مکی زندگی میں بعض اہل کتاب ایمان لے آئے تھے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مکی زندگی کے دوران میں بھی بعض اہل کتاب ایمان لے آئے تھے.وَالَّذِیْنَ یَفْرَحُوْنَ میں جن لوگوں کی خوشی کا ذکر کیا ہے میرے نزدیک وہ نجاشی اور اس کے ساتھی تھے.جو ہجرت حبشہ کے وقت سے ہی ایمان لاچکے تھے.حضرت جعفرؓ نے جب ان کو قرآن مجید سنایا تو نجاشی نے کہا کہ میرا بھی یہی ایمان ہے.مگر چونکہ ابھی ان کا ایمان ظاہر نہ ہوا تھا وہ صرف مومنوں کی ترقیات کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے تھے.اس لئے یُؤْمِنُوْنَ نہیں فرمایا بلکہ یفرحون فرمایا ہے.اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ سے مسلمان بھی مراد ہوسکتے ہیں کہ وہ اسلام کی ترقی کی بشارتوں اور اپنے نیک انجام کی خوشخبریوں کو پاکر خوش ہوتے ہیں.مِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ.احزاب سے مراد وہ تمام قومیں ہیں جو نبی کی مخاطب ہوتی ہیں.مگر ایمان نہیں لاتیں.اس میں یہودی، عیسائی، مشرک اور دوسری تمام اقوام مراد ہیں.يُنْكِرُ کے دو معنی يُنْكِرُ کے دو معنے ہیں.ایک انکار کرتے ہیں.دوسرا یہ کہ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں.یا عجیب سمجھتے ہیں.بَعْضَهٗ اس لئے فرمایا کہ جو حصے ان کے مطابق تھے ان سے وہ خوش ہوتے تھے.صرف اپنے مذہب یا خیالات کے مخالف حصوں پر ہی ان کو اعتراض تھا.
Page 90
قُلْ اِنَّمَاۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ سے یہ بتایا کہ ہر نبی کی تعلیم کا مرکزی نقطہ توحید ہوتا ہے.اسی نقطہ کے گرد میری تعلیم چکر لگارہی ہے.پھر میں اس کو کیونکر چھوڑ سکتا ہوں.دوسرے يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ سے جوا س طرف اشارہ تھا کہ کفار قرآن کریم کے بعض حصہ کو بدلوانا چاہتے تھے اس کا بھی جواب دیا کہ میں تو تابع ہوں.جو حکم ہوتا ہے کہتا ہوں.خدا کے کلام کے بدلنے کا مجھے کہاں حق ہوسکتا ہے.اگر میں اس کو بدلوں تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ میں خدائی کا دعویدار ہوں.پس یہ مجھ سے نہیں ہوسکتا کیونکہ مجھے تو حکم ہی یہی ہے کہ میں ایک خدا کی عبادت کروں.اِلَيْهِ اَدْعُوْا کا مطلب.اِلَيْهِ اَدْعُوْا سے بتایا کہ میرا تو شروع سے دعویٰ ہے کہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں.صرف خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوں.پھر میں تمہاری ناپسندیدگی پر اس قرآن کریم میں کیونکر تبدیلی کرسکتا ہوں.اِلَيْهِ مَاٰبِ میں بتایا کہ میرا سارا معاملہ خدا کے ساتھ پیش آنا ہے تو میں اس کی نافرمانی کیسے کرسکتا ہوں.تم مانو نہ مانو.مجھے اس سے کیا غرض.مانو گے تو خود فائدہ اٹھاؤ گے نہ مانو گے تو میرا کیا نقصان ہے؟ پس میں تمہاری خوشی کے لئے خدا تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کس طرح کرسکتا ہوں.وَ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا١ؕ وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ اور اسی طرح ہم نے اسے مفصل حکم کی صورت میں اتارا ہے اور اگر( اے مخاطب) تو نے اس علم کے بعد جو تجھے بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ١ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا وَاقٍؒ۰۰۳۸ حاصل ہو چکا ہے ان( کفار)کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلہ میں نہ( تو) تیرا کوئی دوست ہو گا اور نہ کوئی بچانے والا(ہوگا).حلّ لُغَات.عَرَبِیًّا.اَعْرَبَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں اَبَانَہٗ وَاَفْصَحَہُ.کسی چیز کو خوب بین اور واضح کر دیا.عَنْ حَاجَتِہٖ اَبَانَ عَنْھَا.حاجت کو کھول کر بیان کیا.کَلَامَہٗ.حَسَّنَہٗ وَاَفْصَحَ وَلَمْ یَلْحَنْ فِی الْاِعْرَابِ بات میں حسن پیدا کیا اور اسے خوب واضح کیا.ا ور تلفظ میں بھی کوئی غلطی نہ کی.بِحُجَّتِہٖ.اَفْصَحَ بِھَا.اپنی بات کھول کر مدلل طور پر بیان کی.اور مفردات راغب میں ہے الإِعْرَابُ: اَلْبَیَانُ کہ اعراب کے معنے بات کو کھولنے اور خوب واضح کرنے کے ہیں.پس حُکْمًا عَرَبِیًّا کے معنے ہوئے مفصل حکم.عَرَبِیًّا کی مزید تشریح کے لئے دیکھو سورۃ یوسف آیت نمبر ۳.
Page 91
عَرَبِیٌّ کا لفظ عرب کی طرف منسوب ہے.اور عَرَبٌ عَرِبَ یَعْرَبُ کی مصدر بھی ہے اور صفت مشبہ بھی.اور نیز یہ عرب کی مصدر ہے اور یہ ملک عرب کا نام بھی ہے اور اس ملک کی اصلی اور پرانی باشندہ قوم کا نام بھی.عَرِبَ کے معانی حسب ذیل ہیں.جن میں سے ہر ایک میں پری اور بھرا ہوا ہونے کا مفہوم پایا جاتا.عَرِبَتِ الْمِعْدَۃُ عَرَبًا تَغَیَّرَتْ وَفَسَدَتْ.زیادہ کھانے سے فساد معدہ ہو گیا.عَرِبَ الْجُرْحُ نُکِسَ وَغُفِرَ وَبَقِیَ اَثَرُہٗ بَعْدَ الْبُرْءِ.زخم اوپر سے اچھا ہوکر اندر سے ازسرنو بھر گیا.اور اس کا منہ بند رہا.تَوَرَّمَ وَتَقَیَّحَ.زخم پھول گیا.اور اس میں پیپ پڑ گئی.فُلَانٌ فَسَدَتْ مِعْدَتُہٗ.اسے بدہضمی ہو گئی.نَشِطَ.اس کے جسم میں چستی پیدا ہو گئی.اور امنگ سے بھر گیا.فَصُحَ بَعْدَ لُکْنَۃٍ.بغیر کسی رکاوٹ کے خوب بولنے لگ گیا اور اس کی صفت مشبہ بھی عَرَبٌ ہی آتی ہے.اَلنَّہْرُ غَمَرَ.اور جب یہ لفظ نہریا دریا کے لئے بولا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں بھر گیا.اور اس کا پانی بہت اونچا ہو گیا.(اقرب) پس عَرَبٌ مصدر کے ان تمام معانی کا قدر مشترک بھرا ہوا ہونا.یا بھر جانا ہوا.جس کے ساتھ یاء نسبت کے لگنے سے اس کے معنے ہوئے خوب بھری ہوئی چیز.کیونکہ یاء نسبت کے لگانے سے وصفی معنے کے علاوہ مبالغہ کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے اور عَرَبٌ صفت مشبہ کے معنے بھری ہوئی چیز کے ہوئے.اور جب اس کے ساتھ یاء نسبت لگائی جائے تو جس طرح اَحْمَرُ کے مقابلہ میں اَحْمَرِیُّکے معنے بہت سرخ کے اور عَبْقَرُ کے مقابلہ میں عَبْقَرِیٌّ کے معنی نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی چیز کے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے معنے ہوں گے.خوب بھری ہوئی چیز اور جب یہ لفظ کسی کتاب کی صفت واقع ہو تو ان معنوں کی رو سے کِتَابٌ عَرَبِیٌّ کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ نہایت پرمعانی کتاب ہے.کیونکہ جس چیز سے کسی کتاب کو بھری ہوئی کہا جاسکتا ہے وہ اس کے معانی اور مطالب ہی ہوسکتے ہیں.اور جب ایک زبان کو اس صفت سے موصوف کریں گے تو اس کا یہ مدعا ہوگا کہ اس کے مفردات نہایت ہی کثیرالمعانی اور وسیع مفہوم رکھنے والے ہیں.اور عَرُبَ عَرَبًا کے معنے ہیں کَانَ عَرَبِیًّا خَالِصًا وَلَمْ یَلْحَنْ: تَکَلَّمَ بِالْعَرَبِیَّۃِ وَکَانَ عَرَبِیًّا فَصِیْحًا.زبان کا ہر ایک نقص سے پاک اور خالص عربی اور خوب واضح ہونا.فصیح عربی بولنا اور اپنے مدعا کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرنا.(اقرب) اور یائے نسبت کے لگانے سے اس کے معنے نہایت فصیح اور خوب واضح ہر ایک نقص سے بالکل پاک کے ہوجائیں گے.اور ان معنوں کی مزید وضاحت اس لفظ کی مختلف تصریفات سے بھی ہوتی ہے.چنانچہ اقرب الموارد
Page 92
میں ہے اَعْرَبَ الشَّیْءَ اَبَانَہٗ وَاَفْصَحَہٗ خوب بین اور واضح کر دیا.عَنْ حَاجَتِہٖ اَبَانَ عَنْھَا کھول کر بیان کیا.کَلَامَہُ: حسَّنَہٗ وَاَفْصَحَ وَلَمْ یَلْحَنْ فِی الْاِعْرَابِ.بات میں حسن پیدا کیا.اور اسے خوب واضح کیا.اور تلفظ میں بھی کوئی غلطی نہ کی.بِحُجَّتِہٖ: اَفْصَحَ بِہَا.اپنی بات خوب کھول کر مدلل طور پر بیان کی.اور مفردات راغب میں ہے اَلْعَرَبِیُّ :اَلْمُفْصِحُ.عربی کے معنی ہیں اپنے مدعا کو خوب صفائی اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا.وَالْاِعْرَابُ اَلْبَیَانُ.اور اعراب کے معنے کھولنے اور واضح کرنے کے ہیں.پس ان معنوں کی رو سے قُرْاٰنٌ عَرَبِیٌّ کے معنی ہوئے ایسی کتاب جو ہمیشہ پڑھی جانے والی اور اپنے مطالب کو نہایت وضاحت کے ساتھ اور مدلل طور پر بیان کرنے والی ہے.اَھْوَاءُ.ھَوٰی کی جمع ہے اور اَلْھَوی کے معنے ہیں اِرَادَۃُ النَّفْسِ.ارادہ.خواہش.فُلَانٌ اتَّبَعَ ھَوَاہُ اِذَا اُرِیْدَ ذَمُّہُ.اور جب فُلَانٌ اَتّبَعَ ھَوَاہُ کا محاورہ بولتے ہیں تو اس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے.اور یہ بول کر مذمت مقصود ہوتی ہے.(اقرب) تفسیر.عَرَبِيًّا کے لفظ سے عربی ہونا مراد نہیں عَرَبِيًّا کے لفظ میں صرف عربی ہونا مراد نہیں کیونکہ عربی تو ہر عرب بولتا ہے.مطلب یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں معانی کی ایسی وسعت ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے اس وسعت کو کوئی پیدا نہیں کرسکتا.پس اگر اسے بدلا جائے تو فوراً اس کی شان میں کمی آجائے گی.کہتے ہیں کسی امیر نے ایک ادیب سے کہا کہ قرآن کی مثل تو بناؤ.اس نے کہا اس کے لئے فارغ دماغ چاہیے.عمدہ باغ عمدہ مکان اور فراغت کی ضرورت ہے.امیر نے سب کچھ مہیا کر دیا.نوکر چاکر دے دیئے.وہ عمدہ لباس پہنتا.عیش کرتا اور خوب سیر کرتا رہتا.چھ ماہ کی مقررہ میعاد کے بعد جب اس امیر نے سوال کیا کہ کیا کچھ تیار کیا تو ادیب نے کاغذوں کا ایک انبار دکھا کر کہا کہ میں اس عرصہ میں فارغ نہیں بیٹھا رہا.میں نے دیانتداری سے کام کیا ہے اور یہ ڈھیر اس کی شہادت ہے.مگر قرآن کی مثل مجھ سے نہیں بن سکی.کیونکہ جو آیت نکالتا ہوں اس میں لکھا ہوتا ہے ہم یوں کر دیں گے، تیرے دشمنوں کو یوں تباہ کیا جائے گا اور تیرے دوستوں کو یوں ترقی دی جائے گی.مگر میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں لکھ سکتا.میں تو روٹی بھی تیری کھاتا ہوں.پس مجھ سے قرآن کی مثل نہیں بن سکی.عَرَبِيًّا کا یہی مطلب ہے کہ اس میں غیر معمولی وسعتِ مضامین رکھی گئی ہے.جو انسانی طاقت سے بالاتر ہے.وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ میں ہر مخاطب بھی مرا د ہے اور آنحضرت ؐ بھی مراد ہو سکتے ہیں وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ.اس میں ہر مخاطب بھی مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہوسکتے ہیں.اور اس صورت میں
Page 93
شان ایزدی کا اظہار ہوگا.کہ تیری اپنی کوئی ہستی نہیں.یہ نَے تو اسی وقت تک دل لبھانے والی آواز سے بجتی ہے جب تک کہ آسمانی بادشاہ کے منہ میں ہے اس کے منہ سے ہٹا لو تو خالی لکڑی ہی لکڑی ہے اور کچھ بھی نہیں.وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ اور ہم نے تجھ سے پہلے (بھی) یقیناًکئی رسول بھیجے تھے اور انہیں بیویاں اور بچے( بھی) دئیے تھے اور کسی رسول ذُرِّيَّةً١ؕ وَ مَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ کےلئے ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ (تعالیٰ) کے اذن کے سواء( اپنی قوم کے پاس) کوئی نشان لاتا ہر زمانہ کی انتہاء کے لئے اللّٰهِ١ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ۰۰۳۹ ( خدا تعالیٰ کی طرف سے )ایک (خاص) حکم ہوتاہے.حلّ لُغَات.أَلْاِذْنُ کے معنے ہیں اَلْاِجَازَۃُ.اجازت.اَلْاِرَادَۃُ.ارادہ.اَلْعِلْمُ.علم.(اقرب) أَ لْاَجَلُ.أَ لْاَجَلُکے معنے ہیں مُدَّۃُ الشَّیْءِ.کسی چیز کی مدّت.وَوَقْتُہُ الَّذِیْ یَحلُّ فِیْہِ.کسی امر کی وہ مدت جب جاکر وہ واقعہ ہوتا ہے.(اقرب) اَلْکِتَابُ اَلْکِتَابُ کے معنے ہیں اَلْحُکْمُ.حکم.اَلْفَرْضُ.فرض.اَلْقَدْرُ.قدر.اندازہ.(اقرب) لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ کے معنے لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ کے معنے ہوئے ہر مدت کے لئے فیصلہ الٰہی میں حکم موجود ہے.کتاب کی اجل نہیں کہا بلکہ اجل کی کتاب کہا ہے.یعنی ہر عمل کا نتیجہ نکلنے کے لئے ایک خاص حکم ہے.ایک خاص وقت ہے.تفسیر.اس آیت میں پہلے مضمون کو دہرایا ہے.یعنی جو مضمون پہلے رکوع میں آیا تھا اسی کو آخر میں دوبارہ بیان کیا ہے.جو یہ ہے کہ جس قسم کے حالات میں پہلے رسول آتے رہے انہی حالات کے ماتحت تو آیا ہے.کفار کا یہی سوال تھا کہ تو بے سامان آیا ہے.سو اس کا یہ جواب فرمایا کہ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے تھے وہ بھی تو اسی طرح بے سامان ہی آئے تھے.ا ن کے ساتھ بھی تیری طرح انسانی حاجتیں لگی ہوئی تھیں.ان کے بھی بیوی بچے تھے.جن کی پرورش کا انہیں انتظام کرنا پڑتا تھا.جسمانی ذمہ داریاں تھیں جنہیں ادا کرنا پڑتا تھا.مگر
Page 94
باوجود حاجات کی موجودگی کے اور سامانوں کے فقدان کے وہ کامیاب ہوئے.بیوی بچوں کا ذکر یہ بتانے کے لئے کیا کہ آزاد انسان زیادہ دلیری سے قربانی کرسکتا ہے.لیکن بیوی بچے کام میں قدم قدم پر روک ہوتے ہیں.پس گویا دوہری روکیں ان کے راستہ میں بھی تھیں.اول سامان نہ تھے.پھر جو سامان میسر تھے ان کے استعمال میں بھی بیوی بچوں کی وجہ سے روکیں تھیں.مگر پھر بھی وہ کامیاب ہوئے.اسی طرح اب محمد رسول اللہ صلعم کامیاب ہوں گے.مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ گو ہم نے انہیں کامیاب کیا.اور یہ عظیم الشان صداقت کا نشان ان کو ملا لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ ان کے لئے لوگوں کی مرضی کے مطابق نشان دکھایا ہو.جو نشان ہم نے مناسب سمجھا وہ دکھایا.قرآن کریم میں جہاں کفار کی طرف سے نشان کے مطالبہ کا ذکر ہو اور ساتھ تشریح نہ ہو وہاںنشان سے مراد عذاب ہوتا ہے.پس اس جگہ بھی عذاب ہی مراد ہے.اور چونکہ اس جگہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا تھا تو کیا روک تھی کہ ان کے ہاتھوں میں سزا بھی رکھ دیتا.تاکہ لوگوں کو حق کی مخالفت کی جرأت نہ رہتی.آخر دنیوی حکومتیں بھی تو اپنے ماتحتوں کو ایک حد تک سزا کا اختیار دیتی ہیں.اس کا جواب لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ کے الفاظ میں دیا جس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نےبنی نوع انسان کی حالت کا اندازہ لگا کر نہ صرف یہ فیصلہ کیاہے کہ کس کس عمل کی کیا کیا پاداش چاہیے بلکہ یہ بھی کہ کس عمل کا نتیجہ کس وقت نکلنا اس شخص اور دوسرے شخصوں کے لئے زیادہ مفید ہوگا؟ اور ہر سزا کے لئے اس نے ایک وقت مقرر کر چھوڑا ہے.اگر وہ سزا نبیوں کے ہاتھ میں رکھتا تو وہ چونکہ عالم الغیب نہ ہوتے وہ سزا لوگوں کے مطالبہ پر دے کر اس حکمت کو باطل کر دیتے.دنیوی حکومتوں اور آسمانی حکومت میں یہ بھی ایک فرق ہے کہ دنیوی حکومتیں جرم کے مطابق سزا تجویز کرکے ہر جرم پر سزا دے دیتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں دیکھتا کہ کس نے جرم کیا ہے بلکہ یہ بھی کہ اس جرم کی سزا کو کس وقت جاری کیا جائے؟ تو زیادہ مؤثر یا زیادہ مفید ہوگی.یہ ایک اہم سوال ہے کہ سزا کا وقت سزا کے اثر کو بہت کچھ بڑھا گھٹا دیتا ہے.اور اس لئے کامل اور بے عیب فیصلہ وہی ہوسکتا ہے جس میں سزا کی تعیین ہی نہ ہو بلکہ سزا کے وقت کو بھی حکمت کے ماتحت معین کیا جائے.لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ میں تقدیم و تاخیر نہیں اس آیت کو مفسرین نے بڑا غلط سمجھا ہے.انہوں نے اس میں تقدیم تاخیر مانی ہے اور اس کے یہ معنی سمجھے ہیں کہ ہر کتاب کے لئے ایک وقت ہے.حالانکہ خدا تعالیٰ کو تقدیم و تاخیر کی ضرورت نہیں.جو لفظ اس آیت میں ہے جس ترتیب سے ہے وہی صحیح ہے.کتاب کی اجل نہیں بتائی.بلکہ اجل کی کتاب کاہی ذکر ہے اور کوئی تقدیم وتاخیر نہیں بلکہ یہ فرماکر کہ ہر مدت کے لئے فیصلہ الٰہی میں حکم موجود ہے ایک
Page 95
نہایت لطیف اور جدید مضمون پر روشنی ڈالی ہے جس کا ذکر اجمالاً اوپر آچکا ہے.خلاصہ یہ کہ نبیوں کو سزا جزاء کا اس لئے اختیار نہیں دیا کہ وہ عالم الغیب نہیں.اور نہیں جان سکتے تھے کہ کس وقت کون سا حکم جاری ہونا چاہیے.آیا سزا کا یا عفو کا یا تاخیر سزا کا؟ اگلی آیت اسی مضمون کی تصدیق کرتی ہے.يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ١ۖۚ وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ۰۰۴۰ جس چیز کو اللہ( تعالیٰ) چاہتا ہے مٹاتا ہے اور (جسے چاہتا ہے) قائم کرتا ہے اور اسی کے پاس( تمام) احکام کی اصل (اور جڑ) ہے.حلّ لُغَات.یَمْحُوْ.مَـحَا سے مضارع کا صیغہ ہے اور مَـحَا الشَّیْءَ کے معنے ہیں زَالَ وَذَھَبَ اَثَرُہٗ.کوئی چیز مٹ گئی اور اس کا نشان جاتا رہا.فُلَانٌ الشَّیْءَ.اَزَالَہٗ وَاَذْھَبَ اَثَرَہٗ.کسی چیز کو مٹایا اور اس کا اثر دور کیا.یعنی مَـحَا کا لفظ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے.(اقرب) یُثْبِتُ.اَثْبَتَ ماضی سے مضارع کا صیغہ ہے اور أَثْبَتَ کے معنے ہیں عَرَفَہُ حَقَّ الْمَعْرِفَۃِ کسی بات کو خوب واضح کیا.حَبَسَہٗ وَجَعَلَہٗ ثَابِتًا فِی مَکَانِہٖ لَایُفَارِقُہٗ.کسی چیز کو اس کی جگہ پر ایسا مضبوط کیا کہ وہ اپنی جگہ سے علیحدہ نہ ہوسکے.الحقَّ أَکَّدَہٗ.حق و پختہ کیا.اِسْمَہُ فِی الدِّیْوَانِ.کَتَبَہٗ.نام رجسٹر میں لکھا.(اقرب) پس یَمْحُواللہُ مَایَشَآءُ وَیُثْبِتُ کے معنے ہوئے کہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے.یعنی اگر چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اگر چاہتا ہے عذاب ٹال دیتا ہے.أَلْاُمُّ کے معنے ہیں اَلْوَالِدَۃُ.ماں.أُمُّ الشَّیْءِ: اَصْلُہٗ.کسی چیز کا اصل.أُمُّ الطَّرِیْقِ.مُعْظَمُہٗ.راستے کافراخ حصہ.(اقرب) اُمُّ الْکِتَابِ کے معنے ہوئے کتاب کی اصل.وَ عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ سے یہ مراد ہے (۱)کہ احکام کی حکمت خدا کو معلوم ہے.(۲)تمام احکام شریعت صفات الٰہیہ پر مبنی ہیں.پس شریعت کی جڑ گویا خدا تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ شریعت کے احکام اسی کی صفات کی شاخیں ہیں.تفسیر.یہ کبھی نہیں ہوتا کہ عذاب کا وقت نہ آیا ہو مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی عذاب دے دے.ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ عذاب کا وقت تو آجائے مگر اس کی کسی حکمت کے ماتحت وہ عذاب ٹل جائے.عذاب کے متعلق دو قانون عذاب کے متعلق دو قانون بیان فرمائے ہیں.ایکيَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ
Page 96
دوسرے وَ يُثْبِتُ یعنے یا عذاب کو مٹا ڈالتا ہے.عذاب دیتا ہی نہیں یا عذاب کو قائم رکھتا ہے.مگر بغیر استحقاق کے عذاب کبھی نہیں آتا.نہ استحقاق سے زیادہ آتا ہے.استحقاق کی حد تک عذاب دینا یا اس سے کم دینا یہ اصول ہمیشہ آسمانی عذابوں میں مدنظر رہتا ہے اور یہی اصل ہر شخص کو مدنظر رکھنا چاہیے.جو بااخلاق بننا چاہے.جو لوگ غصہ کی حالت میں دشمن کو پیس کر رکھ دینا چاہتے ہیں یا عفو کرنا نہیں چاہتے وہ صفات الٰہیہ کے خلاف چلتے ہیں اور کبھی سچے مسلمان نہیں کہلا سکتے.اُمُّ الْكِتٰبِ کے دو معنی ام کے معنے جڑ کے ہیں.پس عِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ کے دو معنے ہوں گے.(۱)احکام کی حکمت خدا تعالیٰ کو ہی معلوم ہے اس لئے اس کی ہدایت سے تم صحیح راستہ معلوم کرسکتے ہو.انسان اپنی ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کے اثر کے نیچے کبھی بھی اس قدر بلند نہیں ہوتا کہ تمام عالم کی ضرورت کو مدنظر رکھ سکے.وہ جو احکام تجویز کرتا ہے نفسانیت سے ملوث ہوتے ہیں.مگر اللہ تعالیٰ کی نظر سب عالم کی ضرورت اور آئندہ نتائج پر بھی ہوتی ہے.اس لئے اس کا حکم کامل اور صحیح ہدایت کے مطابق ہوتا ہے.دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ تمام احکام شریعت صفات الٰہیہ پر مبنی ہیں پس شریعت کی جڑ گویا خدا تعالیٰ کے پاس ہوئی.کیونکہ شریعت کے احکام اسی کی صفات کی شاخیں ہیں.اس میں یہ لطیف نکتہ بیان کیا ہے کہ اخلاق کامل اللہ تعالیٰ کی صفات کی کامل اتباع اور پوری نقل کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتے.جو شخص اچھے یا برے اخلاق کی تشریح انسانی اعمال کو سامنے رکھ کر کرنا چاہے کامیاب نہ ہوگا.نیکی کی تعریف نیکی کی تعریف یہی ہے کہ صفات الٰہیہ کی نقل ہو.اور بدی کی تعریف یہی ہے کہ صفات الٰہیہ کے مخالف ہو.اس تعریف سے وہ سب مشکلات حل ہوجاتی ہیں جو فلسفیوں کو نیکی اور بدی کی تعریف کرنے میں پیدا ہوتی ہیں.تیسرے معنے یہ ہیں کہ چونکہ احکام کا مقصد اسی کو معلوم ہے اس لئے سزا اسی کے اختیار میں ہونی چاہیے.کئی شدید دشمن بعد میں ایمان لے آتے ہیں.جیسے اسلام میں عکرمہؓ.خالدؓ اور عَمروؓ بن عاص کے وجود ہیں.ا للہ تعالیٰ ہی جانتا تھا کہ باوجود اسلام کی مخالفت کے وہ لوگ عذاب سے بچانے کے قابل ہیں کیونکہ کسی دن اسلام کی عظیم الشان خدمات کا موقع پائیں گے.
Page 97
وَ اِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۠ اور جس( عذاب کے بھیجنے) کا ہم ان سےوعدہ کرتے ہیں اگر ہم اس کا کوئی حصہ( تیرے سامنے بھیج کر) تجھے دکھا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ۰۰۴۱ دیں(توتو بھی انکا انجام دیکھ لے گا)اور (اگر)ہم (اس گھڑی سے پہلے) تجھے وفات دے دیں (تو تجھے بعد الموت اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کیونکہ )تیرے ذمہ( ہمارے حکم اور پیغام کا) صرف پہنچا دینا ہے.اور( ان کا) حساب لینا ہمارے ذمہ ہے.حلّ لُغَات.نَتَوَفَّیَنَّکَ ہم تجھے وفات دے دیں.مزید تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورہ یونس آیت نمبر ۴۷.نَتَوَفَّیَنَّ باب تفعل سے فعل مضارع ہے جس کاماخذ وَفَاۃٌ ہے.چنانچہ کلیات ابی البقاء میں لفظ تَوَفّٰی کے ذیل میں ہے وَالْفِعْلُ مِنَ الْوَفَاۃِ اور وفات کے معنی موت کے ہیں.(اقرب) تَوَفّٰی اللہُ زَیْدًا قَبَضَ رُوْحَہٗ.اس کی جان نکال لی.اسے وفات دے دی.اس کی روح کو قبض کرلیا.تُوُفِّیَ فُلَانٌ مَجْہُوْلًا قُبِضَتْ رُوْحُہُ وَمَاتَ.اس کی جان نکال لی گئی اور وہ مر گیا.فَاللہُ الْمَتَوَفِّی وَالْعَبْدُ الْمُتَوَفّٰی.غرض ان معنوں میں اس کے استعمال کے وقت اس کا فاعل اللہ اور مفعول بندہ ہوتا ہے.(اقرب) بَعْضُ کُلِّ شَیْءٍ کے معنے ہیں ایْ طَائِفَۃٌ مِّنْہُ ساری چیز کا ایک بڑا حصہ.وَقِیْلَ جُزْءٌ مِّنْہُ.اور بعض محققین کے نزدیک کسی چیز کے ایک تھوڑے سے حصے پر بھی بَعْضٌ کا لفظ بولا جاتا ہے.وَیَجُوْزُکَوْنُہٗ اَعْظَمُ مِنْ بَقِیَّتِہٖ کَالثَّـمَانِیَۃ مِنَ الْعَشَرَۃِ.اور بعض کا لفظ کسی چیز کے بڑے حصہ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے دس میں سے آٹھ کو بعض کہیں.حالانکہ آٹھ بقیہ دو سے بہت زیادہ ہیں.(اقرب) تواِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ کے معنے یہ ہوئے کہ اگر وعدے کا کوئی حصہ ہم تجھے دکھا دیں زیادہ ہو یا کم.تفسیر.یعنی جب ہماری سزا کا اصول ہی اصلاح اور انصاف ہے نہ کہ غصہ نکالنا تو پھر اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ عذاب کی بعض پیشگوئیاں ٹل جائیں ہوسکتا ہے کہ بعض پیشگوئیاں جو عذاب کے متعلق ہیں پوری ہو جائیں اور تو انہیں دیکھ لے اور بعض ٹل جائیں.مگر اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ آخری حساب تو اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا
Page 98
ہے.جو لوگ ان ٹل جانے والی پیشگوئیوں پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ آخر خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے اور سب حقیقت ان پر کھل جائے گی.جب اصل غرض بلاغ یعنی تبلیغ ہے تو پھر امر تبلیغ کے مقصد کے تابع ہی رکھا جائے گا.نہ کہ تبلیغ و اصلاح کو نظرانداز کیا جائے اور سزا کو مقدم.اَوَ لَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا١ؕ وَ اور کیا انہوں نےدیکھا نہیں کہ ہم ملک کو اس کی (تمام) اطراف سے کم کرتے چلے آرہے ہیں اور فیصلہ (تو) اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ١ؕ وَ هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ۰۰۴۲ اللہ (تعالیٰ) کرتاہے کوئی اس کے فیصلہ کو تبدیل کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے.حلّ لُغَات.نَأْتیْ.اَتٰی سے مضارع جمع متکلّم کا صیغہ ہے اور اَتَاہُ کے معنے ہیں جَاءَ ہٗ.اس کے پاس آیا.وَالْاَمْرَ.فَعَلَہٗ.اور جب اَتٰی کا مفعول اَلْاَمْرَ ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں کام کو کیا.اَتَی الْمَکَانَ.حَضَرَہٗ.کسی جگہ گیا.اَتٰی عَلَی الشَّیْءِ.اَنْفَدَہٗ.اس کو ختم کیا.وَبَلَغَ اٰخِرَہٗ اور اس کے انتہاء تک پہنچا.اَتٰی عَلَیْہِ الدَّھْرُ.اَھْلَکَہٗ.زمانہ نے اسے ہلاک کیا.(اقرب) أَطْرَافِھَا.اَطْرَافُھَاطَرَفٌ.اور طَرْفٌ کی جمع ہے اور اَلطَّرَفُ کے معنے ہیں حَرْفُ الشَّیْءِ وَ نِہَایَتُہٗ.کسی چیز کا کنارہ اور اس کی انتہاء.اَلنَّاحِیَۃُ.جانب.طَائِفَۃٌ مِّنَ الشَّیْءِ کسی چیز کا بڑا حصہ.اَلرّجُلُ الْکَرِیْمُ.شریف آدمی اور الطَّرْفُ کے معنے ہیں مُنْتَھٰی کُلُّ شَیْءٍ ہر چیز کا انتہاء اَلْکَرِیْمُ مِنَ الْفِتْیَانِ وَالرِّجَالِ.معزز نوجوان ہو یا بڑا آدمی.اَلْاَطْرَافُ مِنَ النَّاسِ.خِلَافَ الرُّؤُوْسِ.عام لوگ.مِنَ الْاَرْضِ.اَشْرَافُہَا وَعُلَمَآؤُ ھَا.اَطْرَافٌ مِّنَ الْاَرْضِ کے معنے ہیں معزز یا عالم لوگ.ھُوَ مِنْ اَطْرَافِ الْعَرَبِ.اَیْ مِنْ اَشْرَافِہَا وَاَھْلِ بُیُوْتَاتِہَا جب کسی کے متعلق ھُوَ مِنْ أَطْرَافِ الْعَرَبِ کا محاورہ استعمال کریں تو یہ معنے ہوتے ہیں کہ وہ عرب معزز ترین خاندان میں سے ہے.گویا یہ لفظ اضداد میں سے ہے.(اقرب) لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖکے معنے ہیں اَیْ لَارَادَّ لَہٗ وَلَا نَاقِضَ لَہٗ.اس کے فیصلہ کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں یا اس کے حکم کو کوئی توڑنے والا نہیں.(اقرب) تفسیر.عیسائی مصنفین اعتراض کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم سے ثابت نہیں ہوتا کہ محمد (رسول اللہ صلی
Page 99
اللہ علیہ وسلم) نے کبھی کوئی آیت (یعنی نشان) دکھائی ہو.ہاں یہ دعویٰ بے شک ہے کہ دکھائیں گے (A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry ch.2 verse 118).اس آیت میں اس کا کیسا کھلا جواب موجود ہے.فرماتا ہے ہم نے ان کو نشان تو دکھایا ہے مگر یہ دیکھتے نہیں.کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آرہے ہیں.یعنی سابق پیشگوئیوں کے مطابق اسلام کی فتح کے آثار ظاہر ہورہے ہیں.ہر گھر میں سیندھ لگ رہی ہے.ان کی اولادیں مسلمان ہورہی ہیں.اور غلام مسلمان ہورہے ہیں.بڑے لوگوں میں سے بھی ایک حصہ ایمان لارہا ہے.اور عوام میں سے بھی.غرض سوسائٹی کے ہر طبقہ میں سے کچھ لوگ ایمان لارہے ہیں.الارض سے مراد عرب بھی ہوسکتا ہے.یعنی عرب کے اطراف میں اسلام کی اشاعت ہورہی ہے.مثلاً یمن میں لوگ مسلمان ہورہے ہیں.غفار میں سے ابوذرغفاریؓ ایمان لے آئے.مدینہ منورہ میں لوگ اسلام لائے.تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یمن میں سے بعض یہودی اور عیسائی بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے.نَاْتِي الْاَرْضَ سے یہ مراد بھی ہوسکتا ہے کہ ہر قسم کے کفار فنا ہورہے ہیں.کیونکہ اتی اللہ کے معنی قرآن کریم میں سزا اور عذاب کے بھی آتے ہیں.جیسے کہ فرماتا ہے فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا.(الحشر:۳) اللہ تعالیٰ کفار کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے آنے کا ان کو خیال بھی نہ تھا.یعنی ان کو ایسی سزا دی جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا.اس صورت میں یہ معنے ہوں گے کہ ان کے بڑے لوگ بھی سزا پارہے ہیں اور عوام بھی.یا یہ کہ عرب کے چاروں گوشوں میں عذاب آرہے ہیں.مطلب یہ کہ کفار ان امور سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے نشان ان میں ظاہر ہورہے ہیں اور اسلام کی ترقی کے سامان پیدا ہورہے ہیں.وَ اللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ١ؕ وَ هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.یعنی اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے.جب خدا تعالیٰ اس رسول کے ساتھ ہے تو اس کے راستہ میں کون روک بن سکتا ہے.خدا تعالیٰ کے حکم کو ٹالنے کی طاقت ہی کسے ہے؟ اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ دشمن کی باتوں سے نہ گھبرائے.اللہ تعالیٰ کے حکم کوحاصل کرنے کی کوشش میں لگارہے.وَ هُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جلدی حساب لینا شروع کردیتا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب وہ حساب لینے لگے گا تو جلدی سے لے لے گا.یوں تو وہ عذاب میں تاخیر ہی کرتا ہے مگر جب
Page 100
حساب لینے پر آتا ہے تو فوراً لے لیتا ہے اور اس کے حکم میں کوئی روک نہیں بن سکتا.وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا١ؕ يَعْلَمُ اور جو( لوگ) ان سے پہلے تھے انہوں نے (بھی انبیاء کے خلاف اسی طرح مخالفانہ) تدبیریں کی تھیں( مگر ان کی مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ١ؕ وَ سَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى کوئی پیش نہ گئی) پس تدبیر کرنا تو کلی طور پر اللہ (تعالیٰ) ہی کے اختیار میں ہے ہر شخص جو کچھ (بھی) کرتا ہے وہ (یعنے الدَّارِ۰۰۴۳ اللہ) اسے جانتا ہے اوران کافروں کو ضرور (اور جلد) معلوم ہو جائے گا کہ اس( آنے والے) گھر کا (اچھا )انجام کس کے لئے (مقدر) ہے.حلّ لُغَات.مَکَرَہٗ کے معنے ہیں خَدَعَہٗ.اس کو دھوکا دیا.اللہُ فُلَانًا.جَازَاہُ عَلَی الْمَکْرِ.جب اللہ تعالیٰ کے لئے مَکَرَ کا لفظ آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکر کا بدلہ دیا.قِیْلَ الْمَکْرُ صَرْفُ الْاِنْسَانِ عَنْ مَقْصَدِہٖ بِحِیْلَۃٍ.بعض نے کہا کہ کسی کو اس کے قصد سے کسی حیلہ کے ذریعہ سے پھیرنے کا نام مکر ہے.وَھُوَ نَوْعَانِ مَحْمُوْدٌ یُقْصَدُ فِیْہِ الْخَیْرُ وَمَذْمُوْمٌ یُقْصَدُ فِیْہِ الشّر.اور مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی.(اقرب) تَکْسِبُ.کَسَبَ میں سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور کَسَبَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں جَمَعَہٗ اس کو جمع کیا.اور جب کَسَبَ مَالًا وَعِلْمًا کہا جائے تو یہ معنی ہوں گے کہ طَلَبَہٗ وَرَبِـحَہٗ.یعنی اس نے مال و علم حاصل کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گیا.وَالْاِثْمَ تَحَمَّلَہٗ اور جب کَسَبَ کا مفعول اَلاِْثم ہو تو ا س کے معنے ہوں گے تَحَمَّلَہٗ.گناہ کا مرتکب ہوا.ا ور کَسَبَ لِاَھْلِہٖ کے معنے ہیں طَلَبَ الْمَعِیْشَۃَ اپنے اہل و عیال کے لئے روزی کو حاصل کیا.(اقرب) تفسیر.يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ.تمہاری تدبیر کس طرح کارگر ہوسکتی ہے جبکہ وہ تمہاری تمام تدابیر کو جانتا ہے اس لئے وہ ان کو توڑ ڈالے گا.جیسے ایک آنکھوں والا کئی اندھوں کی سرکوبی کے لئے کافی ہوتا ہے.
Page 101
وَ سَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ یعنی کفار جو تدابیر کرتے ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں مگر ان کے برخلاف جو تدابیر ہم اختیار کررہے ہیں ان کا ان کفار کو کوئی علم نہیں ہوسکتا.اس لئے جب کفار کو نقصان پہنچ جائے گا تبھی انہیں معلوم ہوگا کہ انجام کس کے ہاتھ میں ہے.یہاں س زور دینے کے لئے آیا ہے یعنی کفار ضرور جان لیں گے کہ انجام کس کا اچھا ہے؟ اور اس کے معنوں میں قریب کے زمانہ پر بھی دلالت ہوتی ہے اور جاننے کے ایک معنے تو یہ ہیں کہ بالضرور انجام مسلمانوں کا ہی اچھا ہوگا.دوسرے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بڑے بڑے کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کو دیکھ کر مریں گے.وَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا١ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ اور جن لوگوں نے (تیرا) انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو( خدا کا) بھیجا ہوا نہیں ہے تو (انہیں) کہہ (کہ) اللہ( تعالیٰ) شَهِيْدًۢا بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ١ۙ وَ مَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِؒ۰۰۴۴ میرے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے اور( اسی طرح پر) وہ( شخص بھی گواہ ہے) جس کے پاس اس (مقدس) کتاب کا علم (آچکا) ہے.تفسیر.نبی کے مخالفین کی دماغی خرابی کی یہ علامت ہے کہ وہ ہر دلیل کو سن کر انکار کرتے ہیں اور واضح سے واضح برہان پر شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دلیل بجائے خود نبی کے سچا ہونے کی علامت ہوتی ہے.کیونکہ جب کسی قوم کے علماء کی یہ حالت ہو کہ وہ واضح اور ظاہر بات کو نہ سمجھ سکیں تو عوام کی حالت لازماً قابلِ رحم ہوگی اور اگر وہ وقت نبی کی آمد کا نہ ہو تو اور کون سا وقت اس کی بعثت کے مناسب ہوسکتا ہے؟ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ان سب دلائل کو سن کر بھی دشمن یہی کہے گا کہ خواہ کچھ کہو میں تو نہ مانوں گا.اور یہی کہوں گا کہ تو رسول نہیں ہے مگر تو اس سے چڑیو نہیں.تو یہی جواب دیجئو کہ میری شہادت خدا تعالیٰ دے رہا ہے.تو مجھے انکار کی کیا پرواہ ہے؟ اسی طرح جو لوگ کتب سماویہ کا صحیح علم رکھتے ہیں وہ میرے شاہد ہیں.پس ان شہادتوں کی موجودگی میں تمہارے انکار کی کیا قدر ہے؟ یہی دو شہادتیں نبیوں کو فتح دیتی ہیں.یعنی تازہ آسمانی شہادت اور پہلے انبیاء کی پیشگوئیاں.ان دو گواہوں
Page 102
سے بڑھ کر کبھی کوئی اور شہادت کامیاب ثابت نہیں ہوئی.اس وقت بھی انہی دو شہادتوں پر زور دے کر اسلام کی ترقی کی مہم سر کی جاسکتی ہے.
Page 103
سُوْرَۃُ اِبْرَاہِیْمَ مَکِّیَّۃٌ سورۃ ابراہیم.یہ سورت مکی ہے وَھِیَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ ثَلَاثٌ وَّ خَمْسُوْنَ اٰیَةً وَ سَبْعَةُ رُکُوْعَاتٍ اور بسم اللہ سمیت اس کی تریپن آیتیں ہیں اورسات رکوع ہیں سورۃ ابراہیم مکی ہے جمہور کے نزدیک یہ سورۃ سب مکی ہے.لیکن ابن عباس اور قتادہ کے نزدیک اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا سے اِلَى النَّارِ تک مکی نہیں باقی مکی ہے(بحر محیط زیر آیت ابراہیم ۱ تا ۳ ).نحاس نے حبر سے روایت کی ہے کہ یہ آیتیں بدر کے مشرک مقتولین کے متعلق ہیں.ابوالشیخ نے بھی اسی قسم کی روایت قتادہ سے کی ہے(روح المعانی ابتدائی تعارف سورۃ ابراہیم).سورۃ ابراہیم کا سورۃ ھود سے تعلق اس سورۃ میں بھی وہی پہلا مضمون جاری رکھا گیا ہے.مگر رؤیت پر بنیاد ہے.یعنی واقعات سے مسائل کا زیادہ استخراج کیا گیا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی حالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں.اور پھر بھی وہ رسول بغیر اس کے کہ ظاہری سامان ان کی تائید میں ہوں کامیاب ہوتے رہے ہیں.سورۃ ابراہیم کا خلاصہ مضمون خلاصہ مضمون اس سورۃ کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی اصل غرض ہدایت ہے.لوگ تاریکی میں تھے.اب تو انہیں تاریکی سے نور کی طرف نکالے گا.اس غرض کے لئے ہم پہلے بھی رسول بھیج چکے ہیں.چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی غرض سے آئے تھے اور پھر موسیٰ کی زبانی بتایا ہے کہ پہلے رسول بھی اسی غرض سے آئے تھے.پھر ان سب کی کامیابی کا گر بتایا کہ چونکہ ان کے ساتھ حق تھا اس لئے آخر ان کی بات غالب آئی.پھر سچے کلام کی علامتیں بتائی ہیں اور فرمایا ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ علامتیں قرآن کریم میں موجود ہیں یا نہیں.پھر جو اندھیرے سے باہر نکالے گئے ہیں یعنی مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اس اعلیٰ کلام سے تم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہو.پھر بتایا ہے کہ یہ تغیر جو عرب میں پیدا ہونے والا ہے اس کا آج ہی ہم نے ارادہ نہیں کیا کہ ہم اس کو بدل ڈالیں بلکہ یہ قدیم سے ہمارے مدنظر ہے.جن تغیرات کو ہم آج پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں کے لئے ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے دعا کی تھی.بلکہ مکہ کو قائم ہی انہیں تغیرات کے لئے کیا گیا ہے.اور ہم جو غیر معمولی طور پر مکہ کے لوگوں کو رزق پہنچاتے رہے ہیں وہ بھی ان آئندہ آنے والے تغیرات کی وجہ سے تھا.پھر ہم آج انہیں کس طرح
Page 104
بھلا سکتے ہیں.پھر مومنوں کو توجہ دلائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہم تمہارے فرائض بیان کرچکے ہیں.تمہیں وہ ذمہ داریاں کبھی نہیں بھلانی چاہئیں اور کفار کو ڈرایا ہے کہ ابراہیم نے اس نیت سے مکہ کی بنیاد رکھی تھی کہ یہ توحید کا مرکز ہو.اب اگر تم شرک نہ چھوڑوگے تو تم کو یہاں سے دور کر دیا جائے گا.اور تمہاری ہلاکت توحید کی تصدیق کے لئے ایک دلیل بن جائے گی.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ (تعالیٰ) کا نام لے کر (شروع کر تا ہوں) جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کر نے والا ہے.الٓرٰ١۫ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ الٓرٰ.(یہ) ایک کتاب ہے جسے ہم نے تجھ پر اس لئے اتارا ہے کہ تو تمام لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے ظلمات اِلَى النُّوْرِ١ۙ۬ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِۙ۰۰۲ سےنکال کر نور کی طرف یعنی (اس) کامل (طور پر) غالب( اور) کامل محمود( ہستی تک پہنچنے )کے راستہ کی طرف لائے.حل لغات.لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْر.أَخْرَجَہٗ اور أَخْرَجَہٗ مِنْ کَذَا اِلٰی کَذَا کے معنوں میں فرق ہوتا ہے.اَخْرَجَہٗ کے یہ معنے ہیں کہ اس کو نکالاا ور اَخْرَجَہٗ مِنْ کَذَا اِلٰی کَذَا کے معنے یہ ہیں کہ اس کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ لے گیا.پس لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ کے یہ معنے ہوں گے کہ تو لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے.بِاِذْنِ رَبِّھِمْ اِلَی صِرَاطِ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ.ان کے ربّ کے حکم کے ساتھ اس راستہ کی طرف جو عزیز و حمید کا ہے عزیز کے معنے ہیں أَ لْمَنِیْعُ الَّذِیْ لَایَنَالُ وَلَا یُغَالِبُ وَلَایُعْجِزُہٗ شَیْءٌ وَلَا مِثْلَ لَہٗ.غالب، قادر جسے کوئی چیز عاجز نہ کرسکے اور اس کا کوئی شریک نہ ہو.(اقرب) حَمِیْدٌ جو کامل حمد والا ہو.تفسیر.کتاب خبر ہے.مبتداء محذوف کی جو مثلاً ھٰذَا الْقُرْاٰنُ ہے.یعنی یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے تجھ پر اتاری ہے.قرآن کریم ایک روشنی ہے اس آیت میں بتایا ہے کہ قرآن کریم ایک روشنی ہے جس کے ذریعہ سے محمد رسول اللہ
Page 105
لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال لے جائیں گے.روشنی کی تشریح پھر روشنی کی تشریح اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ سے کی.یعنی عزیز و حمید خدا کا راستہ ہی اصل روشنی ہے.ہم دیکھتے ہیں روشنی کو تو ہر ایک پسند کرتا ہے لیکن روشنی کی تشریح میں لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے.آج کل لوگ کہتے ہیں یہ نئی روشنی کے آدمی ہیں اور مراد جدید فلسفہ اور تہذیب اور اباحت اور لامذہبی کی اتباع ہوتی ہے.کوئی کہتا ہے مسیحیت خدا کا نور ہے.کوئی ہندو مذہب کو کوئی اسلام کو خدا کا نور قرار دیتا ہے.اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسم و رواج اور قشر اور چھلکا خدا کا نور نہیں کہلا سکتا.نور تو خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا نام ہے.جس کا قدم خدا تعالیٰ کی طرف نہیں اٹھا اسے نور کو حاصل کرنے والا کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے.نور کو وہی پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے.صفت عزیز اور حمید علمی و عملی روشنی پر دلالت کرتی ہیں وجود باری پر دلالت کرنے کے لئے اس جگہ دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے.عزیز اور حمید.عزیز کے معنے غالب اور حمید کے معنے قابل تعریف کے ہیں.ان دو صفات کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ ایک عملی روشنی پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا علمی پر.عزیز سے مل کر انسان اپنے دشمنوں پر غالب آجاتا ہے اور ظاہری اندھیرے یعنی تکالیف اور مصائب دور ہوجاتے ہیں.اور حمید سے مل کر انسان اپنے اندرونی دشمن شیطان پر غالب آجاتا ہے اور باطنی اندھیرے یعنی وساوس اور شبہات اور جہالت دور ہو جاتے ہیں.آنحضرت ؐ کے ذریعہ سے عربوں میں پہلی تبدیلی.صفت عزیز کے ماتحت صحابہ دنیا پر حکمران ہوگئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے یہ دونوں کام ہوئے.عربوں کی ذلت اور نکبت و ادبار بھی دور ہوا.اور ان کی جہالت اور شرک اور اخلاقی کمزوری بھی دور ہوئی.ایک طرف وہ سب دنیا کے بادشاہ ہو گئے.دوسری طرف وہ سب دنیا کے معلم ہو گئے.عربوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی حالت اور آپ کے بعد کی تبدیلی کا اس تاریخی واقعہ سے کچھ اندازہ ہوسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب ایرا ن پر چڑھائی ہوئی تو ایران کے بادشاہ نے اپنے کمانڈر انچیف کو یہ کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو کچھ انعام کا وعدہ دے کر جنگ کو ختم کرو.اور انعام بھی نہایت حقیر تھا.یعنی فی سپاہی ایک ایک دو دو دینار(السیرۃ الحلبیۃ ،الفاروق از شبلی نعمانی واقعہ محل).اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب اپنی ہمسایہ قوموں کی نظر میں نہایت غریب اور محتاج اور کم ہمت تھے.لیکن اسلام نے ان کو کیا بنا دیا.وہ اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نہ صرف ایرا ن کو فتح کیا بلکہ شام، فلسطین، مصر، اناطولیہ، آرمینیا، عراق، شمالی افریقہ، ہسپانیہ، افغانستان، ہند اور چین تک بھی پہلی صدی کے اندر فتح کرلئے.
Page 106
صحابہ جو غریب اور متوسط الحال لوگ تھے.ایسے ایسے دولت مند ہو گئے کہ ایک صحابی عبدالرحمٰن بن عوف جب فوت ہوئے تو اڑھائی کروڑ روپیہ ان کا ترکہ نکلا جو آج کل کے لحاظ سے بہت بڑی دولت ہے کیونکہ اس وقت روپیہ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی.آنحضرت ؐ کے ذریعہ سے عربوں میں دوسری تبدیلی دوسری تبدیلی بھی ظاہر ہے.عرب کے لوگ یا تو لکھنے کو عیب سمجھتے تھے اور کسی قسم کا علم بھی ان میں نہ پایا جاتا تھا.ساری دنیا کے علوم کے حامل ہو گئے.تاریخ کی بنیاد انہوں نے ڈالی.صرف و نحو، معانی، بیان، لغت کو انہوں نے کمال تک پہنچا دیا.علوم کی ایجاد فقہ اور فلسفہء فقہ اور منطق اور حکمت اور طب اور سیاست اور انجینئرنگ اور ہندسہ اور الجبرا اور علم کیمیا اور ہیئت وغیرہ.بیسیوں علوم یا ایجاد کئے یا انہیں ادنیٰ حالت سے بڑھا کر کمال تک پہنچایا.اور آج یورپ کے محققین تسلیم کرتے ہیں کہ اگر مسلمان عرب نہ ہوتے تو آج دنیا علم کی اس منزل پر نہ ہوتی جہاں اب ہے.اور روحانیت میں جو عربوں نے ترقی کی اس کی مثال تو ابتداء عالم سے اس وقت تک اور کسی قوم میں پائی ہی نہیں جاتی.اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ١ؕ وَ وَيْلٌ یعنی اللہ (تعالیٰ کے راستہ کی طرف) کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور (اس کا) انکار لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِۙ۰۰۳ کرنےوالوں کے لئے ایک (بہت) بڑی آفت یعنی ایک سخت عذاب (مقدر) ہے.حلّ لُغَات.اَلْوَیْلُ.حَلُوْلُ الشَّرِّ.وَیْلٌ کے معنے ہی مصیبت کا نازل ہونا.وَقِیْلَ ھُوَ تَفْجِیْعٌ اور بعض محققین لغت کہتے ہیں کہ یہ لفظ کسی کے مبتلائے مصیبت ہونے یا اس پر اظہار افسوس کے لئے بولا جاتا ہے.وَوَیْلٌ کَلِمَۃُ عَذَابٍ.نیز یہ لفظ عذاب کے لئے استعمال ہوتا ہے.وَالرَّفْعُ عَلَی الْاِ بْتِدَاءِ اور چونکہ وہ اس مقام پر مبتداء ہوتا ہے اس پر رفع آتا ہے.وَالْوَیْلَۃُ.اَلْفَضِیْحَۃُ وَالْبَلِیَّۃُ اور وَیْلَۃٌ کے معنی رسوائی کے اور مصیبت کے ہیں.(اقرب) تفسیر.اللہ عزیز و حمید کے بعد آیا ہے اس لئے کہ یہاں وہ عطف بیان کے طور پر استعمال ہوا ہے.اور معنے یہ ہوئے کہ عزیز و حمید کے راستہ کی طرف جس سے مراد ہماری اللہ ہے.اسی کا آسمان اور زمین ہے یعنی تمام مخلوق
Page 107
اس کے غالب ہونے پر شاہد ہیں.زمین و آسمان میں ایک ہی قانون نظر آتا ہے اور اسی طرح زمین و آسمان اس کے حمید ہونے پر بھی شاہد ہیں کیونکہ کہیں کوئی نقص یا عیب نظر نہیں آتا.پس جو لوگ ایسے خدا کی طرف جائیں گے وہ یقیناً اپنے اندر ایک خاص اور نیک تبدیلی محسوس کریں گے اور زمین و آسمان پر انہیں بھی حکومت ملے گی.یہ وعدہ کس شان سے پورا ہوا.ایک خلیفہ مدینہ میں بیٹھا ہوا حکم دیتا ہے اور فوراً ساری دنیا اس پر عمل کرنے لگ جاتی ہے.اس قسم کی حکومت کی مثال اور کہاں ملتی ہے؟ مسلمانوں کے ایثار اور ایفائے عہد کی ایک مثال ایسا ہی لفظ حمید کے ماتحت مسلمانوں کی وہ حمد ہوئی کہ اس کی مثال نہیں ملتی.مسلمان کا لفظ ایک ضمانت ہوتی تھی.جس میں کوئی شک نہ کرتا تھا.اس کا وعدہ ایک سماوی تقدیر سمجھی جاتی تھی.جسے کوئی رد نہ کرسکتا تھا.ان کی تعریفوں کی گونج آج بھی دنیا میں سنائی دے رہی ہے.مثلاً ایک یہی واقعہ لے لو کہ ایک دفعہ ایک شخص سے کوئی ایسا جرم ہوا جو اسے سزائے قتل کا حقدار بناتا تھا.جب وہ خلیفۂ وقت کے سامنے پیش ہوا تو اس نے سزا کے سننے کے بعد عرض کی کہ میرے پاس کچھ امانتیں اور ذمہ واریاں اپنے یتیم بھتیجوں کی ہیں.ان کو میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا.مجھے کل اس وقت تک آپ مہلت دیں.وہ کام کرکے پھر حاضر ہو جاؤں گا.خلیفہ نے کہا کوئی ضامن پیش کرو.اس نے خلیفہ کی مجلس میں ایک صحابی (ابوذر) کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے ضامن ہیں.حالانکہ وہ صحابی اس کو بالکل نہیں جانتے تھے.مگر صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اور اس لئے کہ اس نے آپ سے ایک بڑی ذمہ داری کی امید کی تھی اپنی شرافت اور وقار کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی ضمانت دے دی.لیکن مقررہ وقت قریب آ گیا اور وہ نہ پہنچا.لوگوں نے حضرت ابوذرؓ سے پوچھا کہ وہ کون تھا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا.ایک مسلمان جان کر میں نے اس کی ضمانت دے دی.جب اس نے مجھ پر اعتبار کیا تو میں اس پر کیوں اعتبار نہ کرتا.آخر وقت ختم ہونے کو ہوا.تو لوگوں کو حضرت ابوذرؓ کی جان کا خطر پیدا ہوا.لیکن عین وقت پر ایک شخص دور سے بے تحاشا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیااور بے جان ہوکر آ گرا.اور حضرت ابوذرؓ سے معذرت کی کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ بمشکل عین وقت پر پہنچ سکا ہے اور ان کی تشویش کا موجب ہوا ہے… ایک طرف ابوذرؓ کے ایثار کی اور دوسری طرف اس شخص کے ایفاء عہد کی مثال دوسری قوموں میں کہاں ملتی ہے؟ اس واقعہ کو انگریزوں نے اپنی کہانیوں اور نظموں میں بھی درج کیا ہے.ایسی ہی ایک اور مثال ہے.شام کے فتح ہو جانے کے بعد ایک دفعہ عیسائی لشکر عارضی طور پر غالب ہو گیا اور اسلامی لشکر کو کچھ علاقہ چھوڑنا پڑا.اس وقت حضرت عمرؓ کے حکم کے ماتحت مسلمانوں نے اس علاقہ کے سب وصول شدہ ٹیکس واپس کر دیئے کہ جب ہم تمہاری حفاظت نہیں کرسکتے تو
Page 108
ہم تمہارا ٹیکس اپنے پاس نہیں رکھ سکتے.یہ علاقہ بھی عیسائیوں سے آباد تھا.لیکن باوجود اس کے کہ ان کے ہم مذہب فتح پاکر آرہے تھے وہ مسلمانوں کی اس نیک نفسی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ زن و مرد روتے ہوئے شہر کے باہر تک انہیں چھوڑے آئے اور کہتے جاتے تھے کہ اگر عیسائی لشکر آپ کی جگہ ہوتا تو ٹیکس کی واپسی کی جگہ جاتے ہوئے جو کچھ ہمارا تھا وہ بھی لوٹ کر لے جاتا.اور دعائیں کرتے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر واپس لائے.(الفاروق حصہ اول) پہلے زمانہ کے مسلمانوں اور آج کے مسلمانوں میں فرق افسوس کجا وہ زمانہ تھا اور کجا اب مسلمان سب سے زیادہ بے اعتبار سمجھا جاتا ہے.علماء نے غیرمذاہب کو لوٹ لینے کا فتویٰ دیا ہوا ہے.غیرمذہب کی حکومت سے غداری کو دین کا جزو قرار دیا ہوا ہے.غیرمسلموں کے قتل کو ثواب کا موجب بتلاتے ہیں.غرض ہر وہ نیکی جس پر مسلمان کو فخر تھا آج ان میں سے مفقود ہے.اِنَّالِلہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ.جماعت احمدیہ کی ذمہ داری کاش جماعت احمدیہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اسلام کے کھوئے ہوئے متاع کو پھر واپس لائے.اور پھر وہی اخلاق محمد رسول اللہ صلعم کے غلاموں میں دنیا دیکھے.جنہیں دیکھ کر انسان کو خدا تعالیٰ نظر آجاتا ہے.وہ امین ہوں اور ایسے امین کہ خود بھوکے مر جائیں، بیوی بچے بھوکے مر جائیں، لیکن دوسرے کی امانت میں خیانت نہ ہو.وہ سچے ہوں اور ایسے سچے کہ جان جائے مال و دولت جائے، عہدہ جائے لیکن جھوٹ کا ایک لفظ زبان پر نہ آئے.اور نہ آئے وعدہ کریں تو جان کے ساتھ نباہیں اور ارادہ کریں تو سر ہتھیلی پر رکھ کر اسے پورا کریں.ا۟لَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَ جو آخرت کے مقابلہ میں (اس) ورلی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا١ؕ اُولٰٓىِٕكَ اور( دوسرے لوگوں کو بھی )اللہ (تعالیٰ) کے راستہ سے روکتے ہیں.اور اسے کجی اختیار کر کے (حاصل کرنا) چاہتے فِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ۰۰۴ ہیں یہ لوگ دور کی گمراہی میں (پڑے ہوئے) ہیں.حلّ لُغَات.یَسْتَحِبُّوْنَ.اِسْتَحَبَّ سے مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے.اور اِسْتَحَبَّہٗ کے معنی
Page 109
ہیں اَحَبَّہٗ یعنی اس سے محبت کی.اسے چاہا.اِسْتَحْسَنَہٗ.اسے پسند کیا.اَلْکُفْرَ عَلَی الْاِیْمَانِ.اٰثَرَہٗ.کفر کو ایمان پر ترجیح دی یعنی مقدم کیا.(اقرب) یَبْغُوْنَ.بَغَیٰ سے مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے اور بَغَاہُ یَبْغِیْہِ کے معنے ہیں طَلَبَہٗ.اسے طلب کیا.چاہا.یُقَالُ اِبْغِنِیْ ضَالَّتِیْ.اَیْ اُطْلُبْھَا لِیْ چنانچہ اِبْغِنِیْ ضَآلَّتِیْ کا فقرہ بول کر یہ مراد لیتے ہیں کہ میری گمشدہ چیز میرے لئے تلاش کر.(اقرب) پس يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا کے معنے ہوں گے اسے کجی اختیار کرکے حاصل کرنا چاہتے ہیں.تفسیر.جو لوگ ایسی تعلیم کو چھوڑیں گے ان کا انجام واضح ہے.عزیز و حمید کو چھوڑ کر عزت اور حمد کہاں باقی رہ سکتی ہے.مگر فرمایا کفار کو دیکھو خود ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم نہیں ہوتے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو ہی روکتے نہیں بلکہ تعلیم الٰہی میں خرابیاں پیدا کرکے ہمیشہ کے لئے اور لوگوں کو اس کے فوائد سے محروم کرنا چاہتے ہیں.یہ انسان کی سخت بدقسمتی ہوتی ہے کہ ضد میں آکر صداقت کو مٹانے لگ جاتا ہے.اور نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہزاروں آدمیوں کی روحانی موت کا گناہ اس کی گردن پر رکھا جاتا ہے.يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا کے معنے کجی اختیار کرکے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرف ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ خدا کا راستہ مل جائے اور دوسری طرف اپنے غلط رویہ اور گندی عادات کوبھی بدلنا نہیں چاہتے.اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو دھوکا دینے اور اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لئے وہ اپنی خودساختہ باتوں کا نام دین رکھ لیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اور ان کی اولادیں بھی جھوٹی تسلی پاکر نورِ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں.سبیل اللہ سے مراد صداقت مطلقہ ان معنوں کے رو سے سبیل اللہ سے مراد صداقت مطلقہ لی جائے گی.ان معنوں سے ان لوگوں کے خیالات کا رد بھی ہو جاتا ہے.جو کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں نیک اور پارسا لوگ پائے جاتے ہیں.پھر انہیں کیوں خدا رسیدہ نہ قرار دیا جائے.اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی راہ کو تو وہی پاسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول کی اتباع کرے.اگر وہ اس پر مصر ہو کہ اپنے باپ دادا کے راستہ کو نہیں چھوڑوں گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کا متلاشی نہیں.باپ دادا کے راستہ کا متلاشی ہے.پھر جس کا رخ مخالف طرف ہو وہ اس راستہ کی طرف کس طرح پہنچ سکتا ہے جو عوجاً چل پڑے یعنی غلط زاویہ کی طرف بڑھنا شروع کرے.یقیناً اس کی
Page 110
منزل کسی غیرجگہ ہی جاکر ختم ہوگی.سبیل اللہ سے مراد اسلام بھی ہو سکتا ہے اس آیت کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ بظاہر کفار اسلام کے بارہ میں بحث مباحثہ میں لگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اسلام کا نقطۂ نگاہ سمجھنے کی خواہش ہے لیکن درحقیقت وہ ضد اور تعصب سے کام لے کر اسلام کے بارہ میں گفتگو کررہے ہوتے ہیں.اور چونکہ اللہ کے راستہ کو صداقت کی راہوں سے ہی پایا جاسکتا ہے اس لئے وہ ہدایت پانے سے محروم رہ جاتے ہیں.ان معنوں کے رو سے سبیل اللہ کے معنے مخصوص طور پر اسلام کے ہوں گے.وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ١ؕ اور ہر ایک رسول کو ہم نے اس کی قوم کی زبان میں ہی( وحی دے کر) بھیجا ہے.تاکہ وہ انہیں (ہماری باتیں) کھول فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ١ؕ وَ هُوَ کربتائے پھر( اس کے بعد) اللہ (تعالیٰ) جسے (ہلاک کرنا) چاہتا ہے ہلاک کرتا ہے اور جسے (کامیاب کرنا)چاہتا الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ۰۰۵ ہے(اسے) منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے اور وہ کامل (طور پر) غالب( اور) صاحب حکمت ہے.حلّ لُغَات.یُضِلُّ.اَضَلَّ سے مضارع ہے اور اَضَلَّہٗ کے معنے ہیں اَھْلَکَہٗ اس کو ہلاک کر دیا.(اقرب) فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ کے یہ معنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے ہلاک کرتا ہے.بَیَّنَہٗ.اَوْضَحَہٗ کھول کر بیان کیا.(اقرب) اور لِیُبَیِّنَ کے معنے ہوں گے کہ وہ کھول کر بیان کرے.تفسیر.اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ کے معنے اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ کے معنے بعضوں نے تو یہ کئے ہیں کہ رسول کی وحی صرف اس کی قوم کی زبان میں ہونی چاہیے.لیکن یہ صحیح نہیں.ہاں !یہ صحیح ہے کہ اس کی قوم کی زبان میں ضرور وحی ہونی چاہیے کیونکہ وہ پیغام جو اس نے اپنی قوم کو پہنچانا ہے اگر دوسری زبان میں ہوا تو اس کی تبلیغ اس کے لئے مشکل ہو جائے گی.لیکن بطور نشان اور معجزات کسی اور زبان میں الہام ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں.حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے الہاموں پر اعتراض اور اس کا جواب بعض لوگ حضرت مسیح موعود
Page 111
علیہ السلام کے الہاموں پر یہ آیت پیش کرکے اعتراض کرتے ہیں.حالانکہ عربی اور اردو کے سوا آپ کو جن زبانوں میں الہام ہوئے وہ بطور نشان اور معجزات کے ہیں.عربی میں آپ کو اس لئے الہام ہوئے کہ وہ اسلام کی مذہبی زبان ہے.اور اس طرح مسلمانوں کی قومی زبان ہے اور اردو میں اس لئے کہ آپ کے پہلے مخاطب اردودان تھے.اور اگر دیکھا جائے تو آپ کے الہامات کا اصولی حصہ سب کا سب یا عربی میں ہے یا اردو میں.دوسری زبانوں میں جو الہام ہوئے ہیں وہ ایسے نہیں کہ ان کے بغیر تبلیغ میں روک پیدا ہو.وہ صرف ایک مزید تائید اور نشان کے طور پر ہیں.اس آیت سے ویری کا آنحضرت ؐ کی ذات پر اعتراض عیسائیوں نے اور بالخصوص ویری نے اس آیت سے رسول کریم صلعم کی ذات پر اعتراض کیا ہے.ویری صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلعم صرف عرب کے لئے تھے.مگر ساتھ ہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنا جائز ہے.ان کی یہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں.ویری کے اعتراض کا جواب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لئے تھے تو ترجمہ کا سوال ہی کہاں رہا؟ جب دوسری قوموں کا اس سے تعلق ہی نہیں تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور اگر اس آیت سے ترجمہ کرنا جائز ثابت ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ آپ کی رسالت دوسری قوموں کے لئے بھی تھی.حقیقی جواب اس سوال کا یہ ہے کہ یہ مفہوم اس آیت کا ہو ہی نہیں سکتا کہ آنحضرت صلعم عرب کے لئے ہیں.آنحضرت ؐ کے سب دنیا کی طرف مبعوث ہونے کے قرآن مجید سے پانچ دلائل کیونکہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے صاف ثابت ہے کہ آپ سب دنیا کی طرف مبعوث ہوئے تھے.چنانچہ سورۃ اعراف ع۱۹،۲۰ میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِيْ وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ١ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ.اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ١ٞيَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓىِٕثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ١ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ١ۙ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ا۟لَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ١۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.(آیت ۱۵۷ تا ۱۵۹) یعنی میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور اب میں خاص طور پر اس کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو تقویٰ اختیار کریں گے.اور زکوٰۃ دیں گے اور جو لوگ پورے طور پر ہماری آیات پر ایمان لائیں گے.نیز جو کامل طور پر ہمارے اس
Page 112
موعود رسول کی اطاعت کریں گے جس کی بعثت کی بشارات کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں.وہ رسول وقت پر مبعوث ہوکر انہیں نیک کاموں کی تلقین کر رہا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتا ہے.اور وہ ان سے سخت حکموں کے بوجھوں کو اور رسومات کے پھندوں کو جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے دور کرتا ہے.پس جو لوگ اس پر کامل طور پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے اس کی حمایت اور مدد کے لئے ہر ممکن کوشش سے کام لیا اور اس نور کی انہوں نے اتباع کی جو اس رسول کے ساتھ اتارا گیا.صرف ایسے لوگ ہی کامیاب ہوں گے.اے ہمارے رسول! تو یہ اعلان کر کہ اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف اس خدا کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے.اس کے سوا کوئی اور معبود قابل پرستش نہیں.وہ زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے.پس اے لوگو! اللہ پر اور اس کے موعود بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لاؤ.جو خود اللہ کی ذات پر اور اس کے کلمات پر پورا ایمان رکھتا ہے اور اس کی کامل پیروی کی راہوں پر چلو تاکہ تم ہدایت پاؤ.اس میں پانچ دلیلیں اس امر کی دی گئی ہیں کہ نبی کریم صلعم ساری دنیا کے لئے ہیں.پہلی دلیل اہل کتاب کو آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا اول:- اہل کتاب کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو تسلیم کریں.فرمایا اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ یعنی اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رحمت کا انعام دیا جائے گا جو آنحضرت صلعم کو مانیں گے.اگر آپ صرف عرب کے لئے تھے تو اہل کتاب کو رحمت کا انعام حاصل کرنے کے لئے آپ کی اتباع کا کیوں حکم دیا گیا.دوسری دلیل تورات و انجیل میں آنحضرت ؐ کی پیشگوئی تھی دوم:- اس آیت میں ذکر ہے کہ تورات و انجیل میں آنحضرت صلعم کی پیشگوئی ہے.اگر آپ ان کی طرف مبعوث ہی نہ تھے تو ان کے لئے پیشگوئی کی کیا ضرورت تھی.کیونکہ جن کو فائدہ ہوسکتا ہے وہ مکہ والے تھے اور وہ تورات و انجیل کو نہیں مانتے تھے.اور پیشگوئی اس لئے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعہ سے ہدایت ہو.پس تورات اور انجیل میں اسی لئے پیشگوئیاں کی گئی تھیں کہ یہود اور مسیحیوں کے لئے آنحضرت صلعم کا ماننا ضروری تھا.اور قرآن کریم ان پیشگوئیوں کی طرف اسی لئے اشارہ کرتا ہے کہ اس کے نزدیک ان کتب کے ماننے والوں کے لئے بھی آپ کا ماننا ضروری تھا.تیسری دلیل آنحضرت ؐ کا انہیں امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کرنا ہے سوم:- اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلعم انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں.اگر وہ مخاطب نہ تھے تو پھر ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا ضرورت تھی.
Page 113
چوتھی دلیل آپ ؐ پر یہود و نصاریٰ ایمان لانے والے انعام کے وارث ہوں گے چہارم:- اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو یہود و نصاریٰ میں سے آپ پر ایمان لائیں گے وہ کامیاب و مظفر ہوں گے.اگر آپ صرف عرب کی طرف تھے تو پھر تو یہود و نصاریٰ کو ایمان لانے پر سزا ملنی چاہیے تھی نہ کہ انعام ملنا چاہیے تھا.پس ان چاروں دلیلوں سے ثابت ہے کہ اور کسی قوم کی طرف آپ مبعوث تھے یا نہ تھے یہود و نصاریٰ کی طرف تو ضرور تھے.لیکن پانچویں دلیل نے تو بات کو بالکل ہی کھول دیا ہے.دلیل پنجم آنحضرت ؐ ساری دنیا کے لئے رسول ہو کر آئے ہیں پنجم:- دلیل پنجم یہ ہے کہ قرآن کریم نے اوپر کے دلائل کا نتیجہ نکال کر خود ہی فرما دیا ہے.قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا.کہہ دے کہ اے بنی نوع انسان میں تم سب کی طرف رسول ہوکر آیا ہوں.اس دعویٰ نے تو بات کو بالکل صاف کر دیا اور یہود و نصاریٰ کے علاوہ دوسری اقوام کو بھی آپؐ کا مخاطب بنا دیا.آنحضرت ؐ کا ساری دنیا کے لئے مبعوث ہونے کا حدیث سے ثبوت ایک اور آیت میں فرماتا ہے وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا (السبا:۲۹) کہ ہم نے تجھے تمام جہان کی طرف بشیر و نذیر کرکے بھیجا ہے.پھر حدیث میں بھی آتا ہے بُعِثْتُ اِلَی الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ(مسند احمد بن حنبل بروایت جابر بن عبداللہ).میں ہر کالے گورے کی طرف بھیجا گیا ہوں.عرب کبھی بھی اپنے آپ کو اسود نہیں کہتے.بلکہ ہمیشہ احمر کہتے ہیں.اب اسود قوم کوئی اور نکالنی پڑے گی.عربی زبان کے محاورہ کے مطابق وہ عجم ہی ہیں.لغت میں بھی الْاَسْوَدُ وَالْاَحْمَرُ کے معنے الْعَجَمُ وَالعَرَبُ لکھے ہیں.(مجمع البحار ) پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے بُعِثْتُ اِلَی النَّاسِ عَامَّۃً میں سب انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں.(مسند احمد بروایت حضرت جابرؓ) ایک اور روایت میں ان کی جگہ یہ الفاظ ہیں اُرْسِلْتُ اِلَی الْخَلْقِ کَآفَّۃً.میں سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں.( مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب المساجد و مواضع الصلاۃ ، مشکوٰۃ المصابیح کتاب المصابیح باب فضائل سید المرسلین الباب الاول) ان تمام آیات و احادیث سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلعم کی بعثت تمام دنیا کے لئے تھی.اور مسیحی مصنفین کا اعتراض باطل ہے.جس قوم کو نبی پہلے مخاطب کرتا ہے اسی زبان میںاس کو الہام ہوتا ہے اسی طرح ان آیات و احادیث سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جس قوم کو نبی پہلے مخاطب کرتا ہے اس کی زبان میں اس کو الہام ہو تا ہے.اور پھر وہ لوگ بات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں.عربی زبان اُمّ الاَلْسِنَۃ ہے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عربی اُمّ الْاَلْسِنَۃ ہے.کیونکہ جو
Page 114
رسول عرب میں آیا اسی کے سپرد سب دنیا کی اصلاح کی گئی.پس عربی میں نازل ہونے والی وحی کو سب دنیا کے لئے ہدایت قرار دینے سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ عربی کسی نہ کسی رنگ میں ساری زبانوں کی ماں ہے اور دوسری زبانیں اس کی بیٹیوں کی طرح ہیں.آریوں کے ایک اعتراض کا رد.آریوں کے عقیدہ اور قرآن کے بیان میں فرق اس آیت میں آریوں کے اس اعتراض کا بھی رد ہو جاتا ہے جو وہ یوں کرتے ہیں کہ کلام الٰہی ایسی زبان میں آنا چاہیے جسے کوئی بولتا نہ ہو.تاکہ سب میں برابری رہے(ستیارتھ پرکاش چودھواں باب).مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسی زبان میں وحی ہونی چاہیے جس کو لوگ بولتے ہوں.تاکہ نبی ان کو سمجھا سکے اور وہ سمجھ سکیں.جس زبان کو دنیا نہ بول سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے اس میں کلام الٰہی آ نے کا فائدہ کیا ہوا.آریوں کا یہ عقیدہ اس طرح بھی غلط ہے کہ جب وید نازل ہوئے اگر اسی وقت رشیوں نے اسے نہیں سمجھا تو ان کا نزول بے فائدہ ہو جاتا ہے.اور اگر ان کو وید سمجھا دیا گیا تھا تو پھر برابری نہ رہی.اور اگر اس وقت لوگ موجود تھے اور انہیں بھی سمجھا دیا گیا تھا تو گو اس وقت کے لوگوں کے لئے برابری ہو گئی مگر جو لوگ بعد میں پیدا ہوئے ان کے لئے برابری کہاں رہی.اب تو پنڈت تک ویدوں کی زبان سے ناواقف ہورہے ہیں.ہندوستان کی آئندہ زبان اردو ہوگی چونکہ اس زمانہ کے مامور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر عربی کے بعد اردو میں الہام زیادہ کثرت سے ہوا ہے.میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو مدنظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ آئندہ زبان ہندوستان کی اردو ہوگی اور دوسری کوئی زبان اس کے مقابل پر نہیں ٹھہر سکے گی.تبیین کے بعد ہی گمراہی کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ کے بعد یُضِلُّ اللہُ لانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اگر سمجھنے کے سارے سامان نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ گمراہ قرار نہیں دیتا.الزام ہمیشہ اسی وقت قائم کیا جاتا ہے جبکہ پہلے سمجھایا جاچکا ہو.گویا تَبْیِیْن کے بعد ہی گمراہی کا فتویٰ لگایا جاسکتا ہے.اس سے معلوم ہوا کہ جس قوم کو کسی بات کا یقینی علم نہ پہنچے اس وقت تک ان کو نہ ماننے کی وجہ سے سزا نہیں دی جاسکتی.غیر مبایعین کے الزام کی تردید اس ضمن میں ہی میں وہ الزام بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو غیرمبایعین کی طرف سے ہم پر لگایا جاتا ہے کہ گویا ہم ہر شخص کو قابل سزا سمجھتے ہیں.خواہ اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ پہنچا ہو یا نہ.یہ الزام غلط ہے.ہم یہ اعتقاد کیسے رکھ سکتے ہیں جب کہ قرآن شریف میں صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تباہی کا فتویٰ اسی وقت لگتا ہے جبکہ تَبْیِیْن ہوچکی ہو.وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ کے معنی وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.وہ غالب ہے.سزا دے سکتا ہے لیکن حکیم ہے.
Page 115
اس لئے جب تک سزا کے وجوہ نہ ہوں اس وقت تک سزا دیتا نہیں.وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ اور( تجھ سے پہلے) ہم نے موسیٰ کو( بھی) اپنے نشانات کےسا تھ یہ( حکم دے کر) بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ظلمات سے الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ١ۙ۬ وَ ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ نکال کر نور کی طرف لا.اور انہیں اللہ( تعالیٰ) کے انعام اور اس کے عذاب یاد دلا.(کیو نکہ) بلا شبہ اس میں ہر ایک لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ۰۰۶ پور ے صابر (اور)پورے شکر گذار کے لئے کئی نشان( پائے جاتے) ہیں.حلّ لُغَات.وَذَکِّرْھُمْ.ذَکَّرَالنَّاسَ وَعَظَھُمْ ذَکَّرَالنَّاسَ کے معنے ہیں کہ اس نے لوگوں کو نصیحت کی.ذَکَّرَہٗ جَعَلَہٗ یَذْکُرُ.اس کو یاد دلایا (اقرب) اَیَّامُ اللہِ نِعَمُہٗ وَنِقَمُہٗ.اَ یَّامُ اللہِ سے مراد اللہ تعالیٰ کے انعامات اور عذاب ہیں (اقرب) پس ذَکِّرْھُمْ بِاَ یَّامِ اللہِ کے یہ معنے ہوں گے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور انعامات یا ددلا.صَبَّارٌ صَبَرَ سے مبالغہ کا صیغہ ہے.یعنے بہت صبر کرنے والا.صَبَرَ کے لئے دیکھو رعدآیت نمبر ۲۳.شَکُوْرٌ شَکَرَ سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور شکر کبھی بغیر صلہ اور کبھی ل کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے.یعنی شَکَرَہٗ وَشَکَرَلَہٗ اور اگر شَکَرَ کا ’’ل‘‘ صلہ آئے تو یہ زیادہ فصیح سمجھا جاتا ہے اور شَکَرَہٗ وَشَکَرَلَہٗ کے معنے یہ ہوتے ہیں أَثْنٰی عَلَیْہِ بِمَا اَوْلَاہُ مِنَ الْمَعْرُوْفِ.کہ کسی کے احسان کے باعث اس کی تعریف کی.گویا اقرارِ احسان اظہارِ قدر کے ساتھ شکر کہلاتا ہے اور کثرت کے ساتھ اقرارِ احسان کرنے والے کو شکور کہتے ہیں.تفسیر.مسلمانوں کو صبر اور شکر کرنے اور استقلال سے کام کرنے کی نصیحت فرمایا کہ جو کام تیرے سپرد ہوا ہے ویسا ہی کام موسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوا تھا.پس تیرے متعلق بحث کرتے ہوئے مخالف اور موافق کو موسیٰ کے حالات مدنظر رکھنے چاہئیں.یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ کے معاملے میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لئے نشانات ہیں.یعنی جیسے موسیٰ کی قوم نے صبر کیا تھا اور نتیجہ اچھا نکلا تھا بعینہٖ اسی طرح مصائب آئیں گے.جب تک مسلمان استقلال سے کام نہیں کریں گے کامیابی مشکل ہے.اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ
Page 116
موسیٰ کی قوم نے انعام کے بعد شکر نہ کیا اور سزا پا گئی.تمہیں چاہیے کہ انعامات الٰہیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرو اور ان کی بے وقعتی نہ کیا کرو.اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تمہارے لئے بھی اچھا نتیجہ نہ نکلے گا.ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ کے دو معنی ذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ سے یہ بتایا ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کے طریق یہ ہیں کہ (۱)نعمائے الٰہی کی طرف توجہ دلائی جائے.اور (۲)سزاؤں سے خوف دلایا جائے.کیونکہ ایام اللہ سے مراد خاص انعامات یا خاص سزاؤں کے ایام ہوتے ہیں.خدا تعالیٰ کی گرفت اور سزا پر زور دئیے جانے کی وجہ آج کل کے تعلیم یافتہ اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ خوف سے جو ایمان پیدا ہو وہ ایمان نہیں.حالانکہ یہ تعلیم فطرت کے خلاف ہے.دنیا کا بہت سا حصہ ایسا ہے جو نیکی کی طرف پہلا قدم خوف سے اٹھاتا ہے.اگر خدا تعالیٰ کی گرفت اور سزا پر زور نہ دیا جائے تو یہ طبقہ بالکل نیکی سے محروم رہ جائے گا.کامل ہدایت وہ نہیں جو صرف کاملوں کے لئے ہو کامل ہدایت وہ ہے جس میں ادنیٰ حالت کے انسانوں کے لئے بھی علاج موجود ہو.وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اور( اے مخاطب تو اس وقت کو بھی یاد کر) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا (کہ اے میری قوم) تم اپنے پر اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ۠ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَ اللہ (تعالیٰ) کا(اس وقت کا) انعا م یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کے ساتھیوں سے اس حالت میں بچایا تھا کہ وہ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ١ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ماردیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے.اور اس میں بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌؒ۰۰۷ تمہارے رب کی طرف سے( تمہارے لئے) بڑا( بھاری) امتحان تھا.حل لغات.یَسُوْمُوْنَکُمْ سَامَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور سَامَہٗ فُلَانًا اَ لْأَمْرَ
Page 118
بلاء کے معنی امتحان کے ہیں خواہ بذریعہ عذاب لیا جائے یا بذریعہ انعام.چونکہ بنی اسرائیل کی آزمائش لڑکوں کے قتل سے اور لڑکیوں کو بچا کر کی گئی تھی اس لئے بلاء کا لفظ استعمال کیا گیا جو دونوں قسم کے امتحانوں پر دلالت کرتا ہے.وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَىِٕنْ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تمہارے رب نے (انبیاء کے ذریعہ سے) اعلان کیا تھا کہ( اے لوگو) اگر تم كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ۰۰۸ شکر گذار بنےتو میں تمہیں (اور بھی) زیادہ دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو( یاد رکھو کہ) میرا عذاب یقیناً سخت (ہوا کرتا) ہے.حل لغات.تَأَذَّنَ تَأَذَّنَ الرَّجُلُ.اَقْسَمَ.تَاَذَّنَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں قسم کھائی.تَأَذَّنَ الْاَمْرَ.(متعدّی) اَعْلَمَہٗ کسی معاملہ کی اطلاع دی اور بتلایا.اَلْاَمِیْرُ فِی النَّاسِ نَادٰی فِیْہِمْ یُھَدِّ دُ وَ یَنْھٰی.تَأَذَّنَ الْاَمِیْرُ کے معنے ہیں کہ امیر نے لوگوں میں حاکمانہ اعلان کیا (اقرب) وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ کے معنے ہوں گے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا اور اس بات کی اطلاع دی.کَفَرَ.کَفَرَ نِعْمَۃَ اللہِ وَبِنِعْمَۃِ اللہِ کُفْرَانًا.کے معنے ہیں جَـحَدَ ھَا وَسَتَرَھَا یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور ان کی ناشکری کی اور ان کو ظاہر نہ کیا.وَھُوَضِدُّ الشُّکْرِ.کفر کا لفظ شکر کے مقابل بولا جاتا ہے.وَفِی الْکُلّیَّاتِ اَلْکُفْرُ تَغْطِیَۃُ نِعَمِ الْمُنْعِمِ بِالْجُحُوْدِ اور کلیات میں کفر کے یہ معنے لکھے ہیں کہ محسن کی نعمتوں کا انکار کرتے ہوئے ان پر پردہ ڈالنا اور ان کا اقرار نہ کرنا.(اقرب) پس اِنْ کَفَرْتُمْ کے معنے ہوں گے کہ اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو.شَکَرْتُمْ.شکر کی تشریح کے لئے دیکھو ابراہیم آیت نمبر ۶.تفسیر.تمام ترقیات شکر کے ساتھ وابستہ ہیں اس آیت میں ایک عظیم الشان قانون بتایا ہے کہ تمام ترقیات شکرکے ساتھ وابستہ ہیں.شکر کے معنے جیسا کہ حل لغات میں بیان کیا گیا ہے احسان ماننا اور محسن کی ثناء کرنا ہیں.اللہ تعالیٰ کا شکر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ انسان اس کی دی ہوئی چیز کو عمدگی کے ساتھ اور برمحل استعمال کرے.جب کوئی شخص کسی کی دی ہوئی چیز کو استعمال نہ کرے تو اس کی تعریف کرنا صرف لفظی ثناء ہوگی.شکر نہ ہوگا.
Page 119
شکر میں صحیح استعمال اور صحیح مصرف کا ہونا ضروری ہے شکر کے لئے ضروری ہے کہ صحیح استعمال اور صحیح مصرف بھی ہو.یہ قانون تمام ترقیات کا گر ہے.اگر علم کا صحیح استعمال کیا جائے گا تو علم ضرور بڑھے گا.آنکھ، ہاتھ، ناک، کان غرض ہر عضو جس کا صحیح استعمال کیا جائے وہ ضرور ترقی پذیر ہوتا ہے.یہ ایک عام قانون ہے اس میں ہندو، مسلم یا عیسائی کی کوئی تمیز نہیں.مسلمان مال کا صحیح استعمال نہیں کرتے.وہ گررہے ہیں.مگر ہندو اس کا صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے ترقی کررہے ہیں.مسلمانوں پر ادبار کی وجہ روحانیات کا بھی یہی حال ہے.قرآن کریم ہی کو دیکھو مسلمان اس کا صحیح استعمال کرتے تھے تو نہ فلسفہ اور عقلیات اور نہ عیسائیت اور یہودیت وغیرہ مذاہب اسلام کے مقابلہ کی تاب لاسکے.مگر آج وید، تورات اور انجیل ہر ایک اپنے آپ کو آگے آگے پیش کررہا ہے.اور دوسری طرف علوم عقلیہ اس پر حملہ آور ہیں.کبھی اسلام کفر کو کھاتا تھا آج کفر اسلام کو کھا رہا ہے.جب مسلمان ہی اسلام کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ حکم بھی ناقابلِ عمل ہے اور وہ بھی تو اس کا باقی کیا رہ گیا.اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے کہ اپنے عیب کو اسلام کی طرف منسوب نہ کریں.عمل تو وہ خود صحیح طور پر نہیں کرتے لیکن نتیجہ کی خرابی کو قرآن کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں.وَ قَالَ مُوْسٰۤى اِنْ تَكْفُرُوْۤا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا١ۙ اور موسیٰ نے (اپنی قوم سے یہ بھی) کہا تھا (کہ)اگر تم اور جو( دوسرے لوگ) زمین میں (بستے) ہیں سب (کے فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ۰۰۹ سب) بھی کفر اختیار کر لو تو(اس میں خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ) اللہ( تعالیٰ) یقیناً بے نیاز (اور) بہت ہی تعریفوں والا ہے.حلّ لُغَات.غَنِیٌّ.غِنًی میں سے صفت مشبہ ہے.اور غَنِیَ فُلَانٌ غِنًی وغَنَاءً کے معنے ہیں ضِدُّ فَقَرَ.اَیْ کَثُرَ مَالُہُ وَ کَان ذَا وَفْرٍ.کہ مالدار ہو گیا.اور ہر چیز کثرت سے میسر آ گئی.غَنَی بِہِ عَنْ غَیْرِہِ : اِکْتَفَی بہِ یعنی اس چیز کے میسر آ جانے سے دوسروں کی مدد کا محتاج نہ رہا.اَلْغَنِیُّ: الْمُکْتَفِیْ مِنَ الرِّزْقِ ضرورت کے مطابق رزق والا.وَھُوَ غَنِیٌّ عَنْہُ اَیْ مُسْتَغْنٍ ھُوَ غَنِیٌّ عَنْہُ کے معنے ہیں اس سے بے نیاز (اقرب) علاوہ ازیں غِنًی کے معنے ہیں عَدَمُ الْحَاجَاتِ حاجات کا نہ ہونا.(مفردات) پس غَنِیٌّ کے معنے ہوں گے ایسی ذات جسے
Page 120
کسی قسم کی حاجت نہ ہو.یعنی بے نیاز.تفسیر.حضرت موسیٰ ؑفرماتے ہیں کہ یہ جو خدا تعالیٰ بار بار نبیوں کے ذریعہ ہدایت بھیجتا ہے اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا کو کوئی ضرورت ہے.اس کو کوئی ضرورت نہیں.وہ تمہارے فائدہ کے لئے بھیجتا ہے.ورنہ وہ تو بے احتیاج ہستی ہے.خدا تعالیٰ کا کلام بھیجنا اس کے محتاج ہونے کی دلیل نہیں اس آیت میں اس سوال کا جواب آجاتا ہے جو آج کل کے تعلیم یافتہ کیا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام بھیجنا اس کے محتاج ہونے پر دلالت کرتا ہے.فرماتا ہے کہ غنی کو دوسرے کی کیا احتیاج ہوسکتی ہے.ہاں چونکہ وہ حمید ہے اس لئے ڈوبتوں کو بچاتا ہے.اس میں یہ نکتہ بتایا کہ ہر کام اپنی احتیاج سے نہیں کیا جاتا.بلکہ کبھی کام دوسرے کی احتیاج کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے.جو لوگ خودغرض ہیں وہ اپنے پر قیاس کرکے خیال کرلیتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے احتیاج ہی کے سبب ہوتا ہے.حالانکہ احتیاج اور احسان میں زمین و آسمان کا فرق ہے.اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ کیا جو لوگ تم سے پہلے تھے یعنی نوح کی قوم اور عاداورثمود اور جو ان کے بعد ہوئے ان کی (نسبت) دلوں کو ہلا دینی ثَمُوْدَ١ۛؕ۬ وَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ١ۛؕ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ١ؕ والی خبرتمہیں نہیں پہنچی وہ ایسے نابود ہوئے اور مٹائے گئے (کہ)اللہ (تعالیٰ) کے سواء (اب) انہیں کوئی (بھی) جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْۤا اَيْدِيَهُمْ فِيْۤ نہیں جانتا.(جب) ان کے پاس ان کے رسول( ہمارے) روشن نشان لے کر آئے تو انہوں نے ان کی بات نہ مانی اَفْوَاهِهِمْ وَ قَالُوْۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَ اِنَّا لَفِيْ اور کہا (کہ) جس (تعلیم) کے ساتھ تمہیں بھیجاگیا ہے اس کا (تو) ہم انکار کر چکے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں
Page 121
شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ۰۰۱۰ بلاتے ہو اس کے متعلق ہم ایک بے چین کر دینےوالے شک میں( پڑے ہوئے) ہیں.حلّ لُغَات.اَلنَّبَأُ اَلْخَبَرُ.نَبَأٌ کے معنے ہیں خبر.یُقَالُ اَ تَانِیْ نَبَأٌ مِّنَ الْاَنْبَاءِ چنانچہ اَ تَانِیْ نَبَأٌ مِّنَ الْاَنْبَاءِ کا محاورہ انہی معنوں کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک خبر آئی.وَقَالَ فِی الْکُلِّیَّاتِ اَلنَّبَأُ وَالْاَنْبَاءُ لَمْ یَرِدَا فِی الْقُرْاٰنِ اِلَّا لِمَا لَہٗ وَقْعٌ وَشَأْنٌ عَظِیْمٌ.اور کلیات میں اَلنَّبَأُ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال ایسے واقعہ اور خبر پر ہوتا ہے جو عظیم الشان اور دل ہلا دینے والی ہوتی ہے.(اقرب) پس اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَأٌ کے معنے ہوں گے کیا تمہارے پاس دل ہلا دینے والی خبر نہیں پہنچی.الْیَدُ.الْیَدُ.الْکَفُّ.یَدٌ کے معنے ہیں ہتھیلی.أَوْمِنْ اَطْرَافِ الْاَصَابِـعِ اِلَی الْکَتِفِ نیز ید کا استعمال انگلیوں کے پوروں سے لے کر کندھے تک کے لئے بھی ہوتا ہے.اس کی جمع اَیْدٍ اور یُدِیٌّ اور جمع الجمع اَیَادٍ ہے اور اَیَادِیْ کا اکثر استعمال نعمت اور احسان پر ہوتا ہے.اور ید کے کئی اور معنے بھی ہیں.مثلاً اَلْجَاہُ.عزت.أَ لْوَقَارُ.وقار.یُقَالُ’’ لَہٗ یَدٌ عِنْدَ النَّاسِ.‘‘ چنانچہ جب لَہٗ یَدٌ عِنْدَ النَّاسِ کا فقرہ بولتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو لوگوں کے ہاں عزت و رتبہ حاصل ہے.اَلطَّرِیْقُ.طریق.أَ لْقُوَّۃُ وَالْقُدْرَۃُ.طاقت.وَالسُّلْطٰنُ.وَالْوَلَایَۃُ.غلبہ.یُقَالُ مَالَکَ عَلَیْہِ یَدٌ اَیْ وَلَایَۃٌ.چنانچہ مَالَکَ عَلَیْہِ یَدٌ میں یَد کے لفظ سے مراد ولایت ہی ہے.اَلْمِلْکُ.ملکیت.اَلْجَمَاعَۃُ.جماعت.اَلْغِیَاثُ.فریادرسی.اَلنِّعْمَۃُ وَالْاِحْسَانُ تَصْطَنِعُہٗ نعمت و احسان جو کسی پر کی جائے.وَھٰذَا فِیْ یَدِیْ اَیْ مِلْکِیْ ھٰذَا فِیْ یَدِیْ کے معنے ہیں کہ یہ چیز میری ملکیت ہے اور اَلْاَمْرُ بِیَدِ فُلَانٍ کہہ کر یہ مراد لیتے ہیں اَیْ فِی تَصَرُّفِہٖ کہ معاملہ فلاں کے تصّرف میں ہے.وَیَدُ الرِّیْحِ سُلْطَانُھَا اور جب ید کا لفظ ریح کی طرف مضاف ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں ہوا کی تیزی و تُندی.(اقرب) پس یَد کے مختلف معنوں کے لحاظ سے رَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِيْۤ اَفْوَاهِهِمْکے مختلف معانی ہوں گے.اوّل منکرینِ انبیاء نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹا دیئے.یعنی حیرت زدہ ہو گئے.(۲) انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر رکھا اور نبیوں کو کہا کہ بولو مت.خاموش ہو جاؤ.(۳) منکرین نے نبیوں کے احسانوں کو ان کے مونہوں پر دے مارا.مُرِیْبٌ مُرِیْبٌ.اَرَابَ سے اسم فاعل ہے.اور اَرَابَ زَیْدًا کے معنے ہیں اَقْلَقَہٗ وَاَ زْعَـجَہٗ.کہ زید کو کسی معاملہ نے بے چینی اور گھبراہٹ میں ڈال دیا.(اقرب) اور مریب کے معنی ہوں گے بے چین کر دینے والا.
Page 122
گھبراہٹ میں ڈالنے والا.تفسیر.سب قوموں میں نبی آتے رہے لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ سے نکلتا ہے کہ غیر قوموں میں بھی نبی آتے رہے.عاد اور ثمود کے بعد تو ابراہیمی نسل شروع ہو گئی تھی اور ابراہیمی نسل کے انبیاء کا ذکر قرآن مجید اور تورات میں موجود ہے.پس مِنْۢ بَعْدِهِمْ سے مراد ابراہیمی نسل کے سوا دوسری نسلیں ہیں جن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا.یعنی کتب سماویہ جو ایک حد تک محفوظ ہیں ان میں ان کا ذکر نہیں ہے.اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیمی زمانہ میں بھی غیرقوموں میں نبی آرہے تھے.بعض تاریخوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ اور ثمود کا زمانہ برابر چل رہے تھے.اگر یہ درست ہے تو ظاہر ہے کہ اسی وقت سے ہی غیر قوموں میں نبی آرہے تھے.رَدُّوْا اَيْدِيَهُمْکے معنوں میں مفسرین کا اختلاف رَدُّ وْا اَيْدِيَهُمْ کے متعلق مفسرین میں بہت کچھ اختلاف ہوا ہے.اور زیادہ مشکل لفظ فی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے.اگر علی آتا تو معنے صاف تھے.رَدَّفِیْہِ چونکہ نئی قسم کا محاورہ ہے اس لئے مختلف معانی کئے گئے ہیں.بعض نے اس کے معنے یوں کئے ہیں (۱) کہ ’’منکرین انبیاء نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹا دیئے.‘‘یعنی وہ انبیاء کی باتیں سن کر حیرت سے انگشت بدندان ہو گئے.اور انہوں نے اس کو عجیب بات سمجھا.کسی کی بات سن کر اس طرح منہ پر ہاتھ رکھنا استہزاء اور تمسخر کا ایک طریق ہے.ہمارے ملک میں عورتوں میں اس کا بہت رواج ہے.غالباً منہ پیٹ لینے کا اشارہ اس میں پایا جاتا ہے.فِیْبمعنے عَلٰی (۲) بعض نے فِیْ کے معنے عَلٰی کے کئے ہیں جو لغۃً درست ہیں(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھٰذا).اس صورت میں یہ معنے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر رکھا.اور کہا کہ بولو مت خاموش ہو جاؤ.یہ عام دستور بھی ہے.خاموش کرانے کے لئے منہ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے.یَدٌ کے معنی احسان کے بھی ہوتے ہیں میرے نزدیک اس مشکل کو حل کرنے کے لئے لفظ یَدٌ کے اور معنوں کو بھی دیکھنا چاہیے.لغت میں لکھا ہے کہ یَدٌ کے معنے نعمت اور احسان کے بھی ہوتے ہیں.ان معنوںکو مدنظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کے احسان کو ان کے منہ پر دے مارا.اور کہا کہ اپنی تعلیم تم اپنے گھر لے جاؤ ہم نہیں سنتے.گویا نبیوں کی تعلیم کو حقارت سے ٹھکرا دیا.اور کہا کہ ہم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں.اردو میں بھی اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ایک فارسی جملہ ’’عطاء تو بلقاء تو ‘‘ بولا جاتا ہے.آیت کا اگلا حصہ بھی احسان کے معنوں کی تائید کرتا ہے آیت کا اگلا حصہ بھی انہی معنوں کی تائید کرتا
Page 124
سلطان کے معنے ہیں دلیل.أَلتَّسَلُّطُ.قبضہ وَقُدْرَۃُ الْمَلِکِ.بادشاہ کی طاقت (اقرب) تو فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ کے معنے ہوں گے ہمارے پاس کوئی روشن نشان اور دلیل لاؤ.یا اپنی طاقت کا اظہار کرو.تفسیر.فاطر کا لفظ پیدائش کی ابتدا کے متعلق اشارہ کرتا ہے قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ کُنْتُ لَاأَدْرِیْ مَاھُوَ فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ.حَتَّی اَتَانِیْ اَعْرَابِیَّانِ یَخْتَصِمَانِ فِیْ بِئْرٍ فَقَالَ اَحَدُھُمَا اَنَا فَطَرْتُھَا اَیْ اَنَا ابْتَدَأْ تُھا (اقرب) ابن عباس کہتے ہیں کہ فاطر کے معنے پوری طرح مجھ پر نہ کھلے تھے.لیکن ایک دفعہ میرے پاس دو اعرابی ایک کنوئیں کے بارہ میں جھگڑتے ہوئے آئے اور ان میں سے ایک نے کہا کہ اَنَا فَطَرْتُہَا میں نے اس کنوئیں کو پہلے بنانا شروع کیا تھا.تب اس لفظ کے معنی مجھے معلوم ہوئے.پیدائش کے چار مراتب ابن عباس کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ فاطر کا لفظ پیدائش کی ابتداء کی طرف اشارہ کرتا ہے اور قرآن شریف نے پیدائش کے چار مراتب بیان فرمائے ہیں.پہلا مرتبہ.۱- خلق کا وہ مرتبہ جس سے پہلے کسی قسم کا کوئی وجود موجود نہ تھا.دوسرا مرتبہ۲- خلق کا وہ مرتبہ جب مادہ تو تھا مگر اس سے آگے کوئی چیز متکیّف ہونی شروع نہ ہوئی تھی.تیسرا مرتبہ۳- خلق کا وہ مرتبہ جب اجتماع کے ذریعہ سے مادہ کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں پیدا ہونی شروع ہوئیں اور قوانین تیار ہونے لگے جس کی تکمیل کا نام قانونِ قدرت ہے.چوتھا مرتبہ۴- خلق کا وہ مرتبہ جبکہ ان قوانین کے مطابق خلق میں تکرار شروع ہوا.یعنی نسل اور ولادت وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا.جیسے انسان سے انسان کا پیدا ہونا.غلہ کا غلہ سے نکلنا.فاطرکے لفظ سے دوسرے مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے فَطُوْر کا لفظ چونکہ ایک چیز کے دوسری چیز سے نکلنے پر دلالت کرتا ہے اس لئے فَاطِر کے لفظ سے پیدائش کے دوسرے مرحلہ کو بیان کرنا مقصود ہے.انبیاء کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر وعظ کرتے ہیں.اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے.تو کیا تم کو اللہ کے متعلق شک ہے کہ وہ الہام بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ شک ہے تو بالکل غلط ہے.کیونکہ وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے.اس کی نسبت یہ امید رکھنا کہ وہ مخلوق کو پیدا کرکے روحانی ہدایت کے بغیر چھوڑ دے گا عقل کے خلاف ہے.دوسرے یہ کہ یہ خیال کرنا بھی کہ وہ جسمانی زمین و آسمان تو پیدا کرے گا مگر روحانی زمین و آسمان کی پیدائش کو نظرانداز کر دے گا عقل کے بالکل خلاف ہے.
Page 125
يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى.ابھی ایک سوال باقی تھا اور وہ یہ کہ کفار کہہ سکتے تھے کہ ہمیں یہ تو شک نہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف بلاسکتا ہے یا نہیں.ہم تو یہ کہتے ہی کہ وہ بڑی شان والا ہے اس کی شان کے خلاف ہے کہ ہم جیسے حقیر وجودوں کو بلائے.(یہ خیال اب بھی تعلیم یافتہ طبقہ میں پھیلا ہوا ہے) تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑی شان والے کی شان کے خلاف تو یہ امر ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو اپنی مدد کے لئے بلائے نہ یہ کہ وہ چھوٹوں کی مدد کے لئے خود آئے.یہ فعل تو اس کی شان کے عین مطابق ہے.ہمارا یہ تو دعویٰ نہیں کہ خدا تعالیٰ تم کو اس لئے بلاتا ہے کہ تم سے کوئی فائدہ اٹھائے.بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس لئے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تا تمہاری احتیاج کو دور کرے.اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے.اور تمہیں ایک نئی زندگی عطا کرے.اس پر ان کا یہ اعتراض نقل کیا کہ اگر ایسا ہوتا تو خدا تعالیٰ کوئی اپنی شان کے مطابق پیغامبر بھیجتا نہ کہ ہمارے جیسے ایک انسان کو بھیج دیتا.تم تو ہماری ہی طرح کے ایک بشر ہو تم کو خدا نہیں بھیج سکتا تھا.پس معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ سب باتیں محض ہم پر حکومت کرنے کے لئے بنا رہے ہو.تاکہ ہمیں اپنے آباء کی اطاعت سے ہٹا کر اپنی فرمانبرداری میں لگاؤ.اگر ہمارا یہ شبہ غلط ہے تو نشانات کے ذریعہ سے اس امر کو ثابت کرو کہ تم ہم سے بالا ہستی ہو.قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَ لٰكِنَّ ان کے پیغمبروں نے انہیں کہا (کہ یہ سچ ہے کہ) ہم تمہاری (ہی)طرح کے بشر ہیںلیکن(ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ) اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ١ؕ وَ مَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ اللہ (تعالیٰ) اپنے بندوں میں سے جس پرچاہتا ہے(خاص) احسان کرتا ہے.اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ١ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ ہے کہ اللہ (تعالیٰ) کے حکم کے سوا تمہارے پاس کوئی نشان لائیں.اور مومنوں فَلْيَتَوَكَّلِالْمُؤْمِنُوْنَ۰۰۱۲ کو اللہ( تعالیٰ) پر ہی توکل رکھنا چاہیے.تفسیر.اس پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم تمہاری ہی طرح کے آدم ہیں لیکن یہ تو
Page 126
سوچو کہ جسے بھی خدا تعالیٰ چنتا آخر وہ اس کی مخلوق میں سے ہی ہوتا اور اس کی دی ہوئی طاقتوں کے ساتھ ہی آتا.آنے والا خدا تعالیٰ کا شریک یا غیر مخلوق تو ہو نہیں سکتا تھا.کیونکہ ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں.اور جب بہرحال اس نے مخلوق ہی میں سے ہونا تھا تو اس پر کیا اعتراض کہ اس نے انسانوں کو اس کام کے لئے کیوں چنا.اپنے بندوں میں سے جسے اس نے چاہا چن لیا.تم اس کے اختیارات کو محدود کرنے والے کون ہو؟ انبیاء بشریت سے بالا نہیں ہوتے باقی جو تم ہم سے ایسی دلیل کا مطالبہ کرتے ہو کہ ہم اپنی فضیلت تم پر ثابت کریں تو یہ مطالبہ ہمارے دعاوی کے خلاف ہے.ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم بشر سے بالا ہیں.بلکہ بشر رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور صرف یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر نشان دکھاتا ہے اور ہمارا اس کی مدد پر انحصار ہے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ ہم خود کوئی معجزہ دکھاتے ہیں.اور جو اصولِ دین ہم پیش کرتے ہیں ان کے رو سے تو وہ شخص مومن ہی نہیں کہلا سکتا جو اپنی ذاتی فضیلت کو پیش کرے.وہ تو کافر ہے مومن نہیں.وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا١ؕ وَ اور ہمیں( ہوا) کیا ہے کہ ہم اللہ (تعالیٰ) پر توکل نہ کریں حالانکہ اس نے ہمارے( مناسب حال) راستے ہمیں لَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَيْتُمُوْنَا١ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ دکھائے ہیں اورجو دکھ تم نے ہمیں دے رکھا ہے اس پر ہم یقیناً صبر کرتے چلے جائیں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو تو الْمُتَوَكِّلُوْنَؒ۰۰۱۳ اللہ (تعالیٰ) پرہی بھروسہ کرنا چاہیے.حل لغات.ھَدٰنا.ھَدَی کی تشریح کے لئے دیکھو سورۃ رعد آیت ۲۸.تفسیر.یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم تو وہم بھی نہیں کرسکتے کہ خدا تعالیٰ ہماری تائید اور مدد کا محتاج ہے.بلکہ اس کی قدرت کو دیکھ کر ہم نے تو ان طاقتوں کو بھی جو اس نے ہمیں دوسرے انسانوں کی طرح دے رکھی ہیں اسی کے سپرد کر دیا ہے.هَدٰىنَا سُبُلَنَا میں عظیم الشان نکتہ هَدٰىنَا سُبُلَنَا سے یہ بتایا کہنبی کی فضیلت ذاتی فضیلتوں کے سبب سے نہیں
Page 127
ہوتی بلکہ اس امر میں ہوتی ہے کہ وہ انسان کی احتیاج کو ثابت کرکے آسمانی مدد کی ضرورت کو ثابت کرتا ہے.ان الفاظ میں یہ عظیم الشان نکتہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ شریعت ان امور کو بیان کرتی ہے جو انسان کے اپنے فائدہ کے لئے ہوتے ہیں.یہ مضمون سُبُلَنَا (ہمارے راستے) کے الفاظ سے نکلتا ہے.یعنی وہ راستے جن کی ہمیں اپنی ترقی کے لئے ضرورت ہے نہ کہ خدا کو ان کی ضرورت ہے.دوسرے سبل کا لفظ جمع رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس تعلیم میں انسان کی مختلف ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے اور اپنے وقت کے لحاظ سے یہ مکمل شرائع ہیں.وَلَنَصْبِرَنَّ کے لفظ سے اپنی کمزوری کا مزید اقرار کیا ہے.اور بتایا ہے کہ بجائے اپنی فضیلت اور طاقت کا دعویٰ کرنے کے ہم تو اقرار کرتے ہیں کہ ظاہری سامانوں کے لحاظ سے تم ہم پر غالب ہو.اور ہم جانتے ہیں کہ تم ہم کو ہر قسم کے دکھ دو گے.مگر ہم چونکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہوئے ہیں.ہم ان دکھوں کو پوری طرح برداشت کریں گے.اور ثابت کریں گے کہ اپنی برتری اور فائدہ ہمارے مدنظر نہیں ہے.توکّل علی اللہ سب سہاروں سے آزاد کر دیتا ہے پھروَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ کہہ کر یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہر شخص کو دوسرے کا سہارا ڈھونڈنا پڑتا ہے.کوئی شخص اکیلا اپنی ضروریات پوری نہیں کرسکتا.تو جب سہارا لینا ہی ضروری ہے اور ہر شخص کو سہارا ڈھونڈنا پڑتا ہے تو پھر معمولی سہارا کیوں تلاش کریں.کیوں نہ خدا تعالیٰ پر ہی توکل کریں تا باقی سب سہاروں سے آزاد رہیں؟ اس آیت سے علاوہ اور سبقوں کے مومن کو یہ سبق بھی حاصل کرنے چاہئیں.مومن اپنی ذات کے متعلق صبر اور دینی کاموں کے لئے غیرت سے کام لیتا ہے ۱- مومن کی شان یہی ہے کہ وہ صبر سے زیادہ کام لے.غصہ کم کرے مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر اور غیرت میں فرق ہے.اپنی ذات کے متعلق صبر سے کام لینا چاہیے اور دین کے کاموں کے متعلق غیرت سے مگر ناجائز غیرت نہ ہو جائز غیرت ہو.خدا تعالیٰ پر توکّل نہ کرنے کی وجہ کامل یقین سے محرومیت ہے ۲ - توکل کے متعلق تصوف کا یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان سہارے تو ہمیشہ ڈھونڈتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ خدا پر توکل نہیں کرتے.اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل یقین لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا.لیکن نبی چونکہ اس کی شفقتوں کا مشاہدہ کرلیتے ہیں اس لئے وہ اور ان کے پیرو نہایت خوشی سے خدا پر توکل کرتے ہیں.انبیاء کا اصل کام یقین اور توکّل پیدا کرنا ہے اور اصل کام نبیوں کا یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ خدا کے متعلق
Page 128
یقین پیدا کرکے لوگوں کو متوکل بنا دیں.وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۤ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے اپنے( اپنے زمانہ کے) پیغمبروں سے کہا (کہ) ہم تمہیں ضرور اپنے ملک اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا١ؕ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ سےنکال دیں گے یا تم (مجبور ہو کر) ہمارے مذہب میں واپس آجاؤ گے (تو ان تکلیفوں سے بچ سکو گے )جس پر الظّٰلِمِيْنَۙ۰۰۱۴ ان کے رب نے ان پر وحی نازل کی( کہ) ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے.حل لغات.لَتَعُوْدُنَّ.عَادَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے.اور عَادَ اِلٰی کَذَاوَلَہٗ کے معنے ہیں صَارَ اِلَیْہِ.اس کی طرف ہو گیا.وَرَجَعَ اس کی طرف لوٹا.وَقِیْلَ اِرْتَدَّ اِلَیْہِ بَعْدَ مَاکَانَ اَعْرَضَ عَنْہُ.اور بعض عَادَ کے معنے یہ کرتے ہیں کہ کسی چیز سے منہ پھیرنے کے بعد اور اسے ترک کرنے کے بعد پھر اس کی طرف رجوع کیا.وَالْعَرَبُ تَقُوْلُ عَادَ عَلیَّ مِنْ فُلَانٍ مَکْرُوْہٌ.اَیْ صَارَ مِنْہُ اِلیَّ.اور جب عرب لوگ عَادَ عَلَیَّ مِنْ فُلَانٍ مَکْرُوْہٌ کا محاورہ بولتے ہیں تو اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مجھے فلاں سے تکلیف پہنچی.(اقرب) اَلْمِلَّۃُ اَلْمِلَّۃُ.اَلشَّرِیْعَۃُ اَوِ الدِّیْنُ.شریعت اور دین کو ملّت کہتے ہیں.وَقِیْلَ اَلْمِلَّۃُ وَالطَّرِیْقَۃُ سَوَآءٌ.بعض کہتے ہیں کہ ملّت اور طریقہ ہم معنے لفظ ہیں.وَھِیَ اِسْمٌ مِنْ اَمْلَیْتُ الْکِتٰبَ ثُمَّ نُقِلَتْ اِلٰی اُصُوْلِ الشَّرَائِع بِاِعْتِبَارِ اَنَّہَا یُمْلِیْہَا النَّبِیُّ اور ملّت اسم ہے جو اَمْلَیْتُ الْکِتَابَ کے محاورہ سے ماخوذ ہے پھر وہ شریعت کے اصول کے معنوں میں استعمال ہونے لگا.کیونکہ شریعت کے اصول نبی لکھاتا ہے.وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَی الْبَاطِلِ کَالْکُفْرِ مِلَّةٌ وَاحِدَۃٌ اور کبھی یہ لفظ جھوٹے مذہبوں پر بھی بولا جاتا ہے.جیسے اَلْکُفْرُ مِلَّۃٌ وَاحِدَۃٌ کے محاورہ سے ظاہر ہے.وَلَاتُضَافُ اِلی اللہ ِوَلَا اِلٰی آحَادِ الْاُمَّۃِ.اور یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہوتا.اور نہ امت کے کسی فرد کی طرف.یعنی دِیْنُ اللہِ تو کہہ سکتے ہیں مگر مِلَّۃُ اللہِ نہیں کہہ سکتے.اسی طرح قوم کی ملّت کہیں گے زید یا بکر کی ملت کا لفظ نہیں بولیں گے.(اقرب) پسلَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَاکے معنے ہوں گے (۱) ہماری ملّت میں آجاؤ
Page 129
(۲) ہمارے مذہب کو اختیار کرو.(۳)ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ.تفسیر.اپنی عزت قائم رکھنے کے لئے کفار کی ایک دلی خواہش جبکہ کفار نبیوں اور ان کی جماعتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور کامیابی کے دعویٰ پر ناراض ہورہے ہوتے ہیں.ان کے دلوں میں ایک باریک خواہش پائی جاتی ہے کہ یہ ہماری طرف جھکیں اور ہماری تھوڑی سی دلجوئی کریں.تاکہ ان کا دعویٰ برتری کا ٹوٹ جائے.اور ہماری بھی کچھ عزت بنی رہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کفار آپ کے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ اگر یہ ذرہ بھی نرمی کردے تو ہم سب مخالفت چھوڑ کر اس سے صلح کرلیں گے.لیکن آپ نے صاف فرما دیا کہ یہ لوگ سورج کو دائیں اور چاند کو بائیں بھی لا کھڑا کریں تو میں یہ بات نہیں مان سکتا(سیرت النبی لابن ہشام زیر عنوان مبادۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ وما کان منھم).صلح کی خواہش پوری نہ ہونے پر کفار کا آخری حربہ اس پر مخالفوں نے آنحضرتؐ کی ذات بابرکات پر اور آپ کے صحابہؓ پر ایسا حملہ شروع کیا کہ جسے آخری حملہ کہنا چاہیے جس کا اختتام ہجرت پر ہوا.اس قسم کے واقعات ہر نبی کو پیش آتے ہیں اور اس آیت سے پہلے کی آیات میں کفار کی اس خواہش کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا تبھی بار بار توکل کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ ہم تمہاری تمام ایذاؤں کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں.اس پر کفار نے سمجھ لیا کہ اب یہ لوگ کسی ایسی صلح پر تیار نہیں جس میں ہماری بھی کچھ عزت رہ جائے.اور انہوں نے وہی دھمکی ان کو دی جو رسول کریم صلعم کو بعد میں کفار مکہ نے دی.یعنی اب ہم بھی صلح پر تیار نہیں.یا تو پوری طرح ہمارے مذہب میں شامل ہو گے یا ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے.زمین سے نکال دینے کے معنے مار دینے کے بھی ہیں زمین سے نکال دینے کے معنے صرف جلاوطن کردینے کے نہیں ہیں بلکہ مار دینے کے بھی ہیں.درحقیقت یہ ایک کامل بے تعلقی کا اعلان ہے.یعنی جب تم اپنے دعویٰ کے متعلق کسی معقول سمجھوتہ پر آنے کے لئے تیار نہیں تو ہمارا تمہارا یکجا رہنا ناممکن ہے.آخر یہ ہمارا ملک ہے ہم اکثریت میں ہیں اگر تم ہماری مرضی کے تابع نہیں رہ سکتے تو پھر ہمارے ملک میں رہنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں.باطل پرست اقوام مذہب کو سیاسی اختلاف کا باعث بنا لیتی ہیں عجیب امر ہے کہ ہمیشہ باطل پرست اقوام اپنی طاقت پر ناز کرتی ہیں اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یا تو عقائد بھی ان کی مرضی کے مطابق رکھے جائیں یا ان کے ملک سے لوگ نکل جائیں.آج کل احمدیوں کے متعلق دوسرے مسلمانوں کا ایک حصہ یہی رویہ اختیار کررہا ہے.ہر جگہ احمدیوں کو دکھ دیا جارہا ہے.اور صاف کہا جارہا ہے کہ یا احمدی توبہ کریں ورنہ ہندوستان سے نکل
Page 130
جائیں.ان کو ہمارے ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں اور لطیفہ یہ ہے کہ بعض ہندو مصنف یہی امر مسلمانوں کے متعلق لکھ رہے ہیں.گویا بلاوجہ اختلاف کی خلیج کو وسیع کیا جارہا ہے اور مذہب کو سیاسیات کے میدان میں گھسیٹا جارہا ہے.لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَمیں دو اشارے لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ اس جگہ لَنُھْلِکَنَّکُمْ نہیں فرمایا بلکہلَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ فرمایا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ان میں سے ایمان لانے والے تھے.اس لئے فرمایا کہ جو لوگ ظلم پر قائم رہیں گے ان کو ہی ہم ہلاک کریں گے.لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ تم جو کہتے ہو کہ چونکہ ہمارا ملک ہے اگر ہماری بات نہ مانو گے تو ہم تم کو نکال دیں گے.تو اس طرح خود اپنے خلاف فتویٰ لگاتے ہو کیونکہ زمین تو خدا کی ہے پھر وہ کیوں تمہارے فتویٰ کے مطابق تم کو ہی ہلاک نہ کرے؟ لَتَعُوْدُنَّ کے تین معنی یہاں جو فرمایا ہے اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا.تو یا تو (۱) عَادَ بمعنی صَارَ ہے یعنی ہو گیا کیونکہ نبی تو بچپن سے ہی شرک سے محفوظ ہوتا ہے.پس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ ہماری ملّت میں آجاؤ.ہمارے مذہب کو اختیار کر لو.یا (۲) چونکہ مومن بھی اس کے ساتھ ہی مخاطب تھے اور مومن فی الواقع پہلے ان لوگوں کے ہم مذہب تھے اس لئے کثرت مخاطبین کے لحاظ سے لوٹ آؤ کے الفاظ استعمال کئے گئے.یا (۳) لَتَعُوْدُنَّ کے الفاظ کفار نے اس لئے استعمال کئے کہ گو نبی خدا تعالیٰ کے فضل سے بچپن سے ہی شرک سے محفوظ ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ مشرکوں میں پیدا ہوا ہوتا ہے اس لئے عرفاً وہ ان کی قوم کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے اس کو مدنظر رکھ کر کفار نے ’’لوٹ آؤ‘‘ کے الفاظ استعمال کئے.وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ١ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ اور ان (کی ہلاکت) کے بعد اس ملک میں ضرور تمہیں آباد کردیں گے یہ( وعدہ) اس کے حق میں ہے جو میرے مَقَامِيْ وَ خَافَ وَعِيْدِ۰۰۱۵ مقام سےڈرے اور( نیز) میرے وعید سے ڈرے.حل لغات.اَلْمَقَامُ.مَقَامٌ مصدر ہے اور اسم زمان اور اسم مکان بھی ہے.یعنی قیام کی جگہ یا قیام کا زمانہ.نیز مقام کے معنے ہیں.اَلْمَنْزِلَةُ.رتبہ.درجہ.شان (اقرب) پس ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ کے یہ معنے
Page 131
ہوں گے کہ یہ اس کے لئے ہے جو میرے رتبہ اور میرے مقام اور میری شان سے ڈرے.وَعِیْدٌ وَعِیْدٌ وَعَدَ کا مصدر ہے اور وَعَدَ عِدَۃً وَوَعْدًا اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.اور وَعَدَ وَعِیْدًا برے معنوں میں اور وعدہ کے وقت وعدہ نہ پورا کرنا تو کذب کہلاتا ہے لیکن وعید میں تخّلف کرم کہلاتا ہے اور اچھا سمجھا جاتا ہے اور وعید کے معنے ہیں اَلتَّھْدِیْدُ.دھمکی.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں جمع کا صیغہ قبضہ اور تصرف کے ظاہر کرنے کے لئے ہے پہلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے متکلم مع الغیر کے صیغہ کو استعمال کیا ہے جو کہ جمع کے معنے دیتا ہے.حالانکہ ہلاک کرنے والی اور جگہ دینے والی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واحد ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ قبضہ اور تصرف کا اظہار کرنا مقصود ہے.چونکہ جماعت میں قوت اور طاقت زیادہ ہوتی ہے جہاں قرآن کریم میں قبضہ اور تصرف بتانا مقصود ہوتا ہے اور اسے نمایاں کرکے دکھانا ہوتا ہے.وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں استغناء کا اظہار مقصود ہوتا ہے یا قبضہ اور تصرف پر زور دینا مقصود نہیں ہوتا.وہاں واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے.جمع کے صیغہ کے استعمال کے متعلق صوفیوں کا خیال بعض صوفیوں نے یہ بھی لکھا ہے جس کام کو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے توسط سے کرتا ہے اس کے لئے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے اور جس کام کو خالص امر سے کیا جاتا ہے وہاں مفرد کا صیغہ استعمال فرماتا ہے.ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَ خَافَ وَعِيْدِ سے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ غلبہ اور کامیابی کا وعدہ اس کے لئے ہے جو میرے درجہ کو سمجھتا ہو اور میرے مالک ہونے پر یقین رکھتا ہو.ان کی طرف سے وعید یہی تھا کہ اے مومنو !ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے گویا وعید اپنی ملکیت سے نکالنے کا تھا.ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو تباہ کرکے اپنے رسول کو ان کی جگہ قائم کر دیں گے.الٰہی وعدہ کے پورا ہونے کے لئے اللہ کی عظمت اور اس کا خوف دل میں ہونا ضروری ہے اور پھر فرمایا کہ یہ وعدہ ہمارا اس کو ہی ملے گا جو میرے مقام اور مرتبہ سے اور میرے انذار سے خوف رکھتا ہوگا گویا وعدہ کے پورا ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت نبی کی جماعت کے دل میں ہو اور اس کے عذاب سے وہ خائف ہوں.پس وہ لوگ غلطی پر ہیں جو صرف امت میں سے کہلا کر الٰہی وعدوں کے امیدوار رہتے ہیں.
Page 132
وَ اسْتَفْتَحُوْا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍۙ۰۰۱۶ اور انہوں نے (اپنی) فتح کے لئے دعا کی اور( نتیجہ یہ ہوا کہ) ہر ایک سرکش (اور) حق کا دشمن ناکام رہا.حلّ لُغَات.اِسْتَفْتَحَ.اِسْتَفْتَحُوْا اِسْتَفْتَحَ سے جمع کا صیغہ ہے اور اِسْتَفْتَحَ الْبَابَ کے معنے ہیں فَتَحَہٗ دروازہ کو کھولا.اِسْتَفْتَحَ الشَّیْءَ بِکَذَا اِبْتَدَأَ ہُ اس کو شروع کیا.اور اِسْتَفْتَحَ فُلَانٌ کے معنے ہیں طَلَبَ الفَتْحَ وَاسْتَنْصَرَ اس نے فتح طلب کی اور مدد چاہی.وَمِنْہُ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا اَیْ اِن طَلَبْتُمُ الظَّفَرَ.یعنی اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا کے معنے ہیں.اگر تم مدد چاہو.نیز ھُوَ یَسْتَفْتِحُ عَلَیَّ بِفُلَانٍ کا فقرہ بھی ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں.یعنی وہ میرے خلاف مدد چاہتا ہے.(اقرب) خاب خَابَ.یَخِیْبُ.خَیْبَۃً.لَمْ یَظْفَرْ بِمَا طَلَبَ.خَابَ کے معنے ہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا.کَفَرَ.کفر کیا.اِنْقَطَعَ اَمَلُہٗ.اس کی امید ٹوٹ گئی.خَابَ سَعْیُہٗ اَیْ لَمْ یَنْجَحْ اور خَابَ سَعْیُہٗ کے معنے ہیں اس کی کوشش ناکام گئی.(اقرب) جَبَّار جَبَّارٌ.یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اس کے معنے ہوتے ہیں بڑا مصلح اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے والا.جب جَبَّار غیراللہ کی صفت ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں کُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ.سرکش.قانون کی خلاف ورزی کرنے والا.وَالَّذِیْ یَقْتُلُ عَلَی الْغَضَبِ جسے غصہ کی حالت میں قتل سے بھی دریغ نہ ہوتا ہو.(اقرب) عَنَدَ عَنَدَ عَنِ الطَّرِیْقِ وَالْقَصْدِ کے معنے ہیں مَالَ وَعَدَلَ.راستہ یا ارادہ کو ترک کر دیا.اُس سے اِدھر اُدھر ہو گیا.اور عَنِیْدٌ کے معنے ہیں اَلْمُخَالِفُ لِلْحَقِّ الَّذِیْ یَرُدُّہٗ وَھُوَ یَعْرِفُہٗ حق کا ایسا مخالف جو اس کو باوجود سمجھنے کے رد کرتا ہو.(اقرب) پس خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ کے معنے ہوں گے.ہر حق کا مخالف.سرکش.اپنی کوششوں میں ناکام رہا اس کی امیدیں ٹوٹ گئیں.اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا.تفسیر.اِسْتَفْتَحُوْا کی ضمیر انبیاء اور کفار دونوں کی طرف راجع ہو سکتی ہے وَ اسْتَفْتَحُوْا الخ کی ضمیر دونوں طرف پھر سکتی ہے.نبیوں کی طرف بھی اور کفار کی طرف بھی اور سیاق و سباق کے لحاظ سے بھی دونوں ہی معنے ہوسکتے ہیں.جب کفار نے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے تو لازماً نبیوں اور ان کے اتباع نے دعا مانگنی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کفار کے شر سے محفوظ رکھے.
Page 133
وعدہ کے بعد دعا کی ضرورت اگر کوئی یہ کہے کہ خدا تو پہلے وعدہ کر چکا ہے کہ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمْ کہ ہم مومنوں کو ہی جگہ دیں گے تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن باتوں کا خدا تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان کے لئے زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے.کیونکہ اگر وعدہ کے بعد انسان محروم رہ جائے تو یہ امر اس کی سخت بدقسمتی پر دلالت کرے گا.وعدہ کے بعد دعا کی ضرورت قرآن کریم کی ایک اور آیت سے ثابت ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰی رُسُلِکَ (اٰل عمران :۱۹۵) پس مومن کو اس پر اتکال نہیں کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے.بلکہ اگر وعدہ ہو تو تدبیر اور دعا سے اور بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے تا اس کی غلطی سے خدا تعالیٰ کے کلام پر کوئی حرف نہ آئے.انبیاء ہمیشہ موعود امور کے لئے دعا اور تدبیر سے کام لیتے چلے آئے ہیں اور یہ ان کی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کی دلیل ہے.فتح مکہ کے وعدہ کے باوجود آنحضرت ؐ کا دعا اور تدبیر سے کام لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ہی فتح مکہ کا وعدہ کیا گیا تھا.جیسا کہ فرمایا لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ (القصص :۸۶) لیکن باوجود اس کے آپ اس کے لئے دعا بھی کرتے رہے اور تدابیر کرتے رہے.بیس کے قریب جنگیں آپ نے اس مقصد کے لئے کیں اگر وعدہ کے بعد تدبیر ناجائز ہے تو پھر چاہیے تھا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا.پس یہ اصل کہ وعدہ کے بعد تدبیر یا دعا ناجائز ہے جاہلوں کا بنایا ہوا ہے اور دین سے جہالت کے سبب سے گھڑا گیا ہے.جیسا کہ بتایا گیا ہے وَ اسْتَفْتَحُوْا کی ضمیر کفار کی طرف بھی پھر سکتی ہے.اس صورت میں آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ کفار فتح کے لئے کوششیں کرتے ہیں اور فتح کی خواہش کرتے ہیں مگر اگلے جملہ میں فرمایا کہ یہ عجب بے وقوف ہیں ان کے سامنے پہلے مثالیں موجود ہیں کہ نبیوں کے مخالف ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوتے رہے ہیں مگر باوجود اس کے پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نبی کے مقابل کامیاب ہو جائیں گے.مِّنْ وَّرَآىِٕهٖ جَهَنَّمُ وَ يُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍۙ۰۰۱۷ اس (دنیوی عذاب) کے بعد (اس کے لئے) جہنم (کا عذاب مقدر) ہے اور( وہاں) اسے تیز گرم پانی پلایا جائے گا حلّ لُغَات.وَرَآئِہٖ.وراء کے لفظ کے معنے آگے اور پیچھے دونوں کے ہیں.اور اکثر زمانہ کے متعلق استعال ہوتا ہے.اور آگے اور پیچھے دونوں معنوں میں اس لئے استعمال ہوتا ہے کہ کبھی فرض کر لیا جاتا ہے کہ گویا
Page 134
زمانہ انسان کے پیچھے چلا آرہا ہے.اور کبھی یہ فرض کیا جاتا ہے کہ انسان اس کی تلاش میں چلا جارہا ہے پس دونوں معنوں میں اس کو استعمال کیا جا تاہے.یعنی اس چیز کے متعلق بھی کہ جو پیچھے سے اس کو آملے گی.اور اس چیز کے متعلق بھی کہ جس کو یہ جا کر آگے مل جائے گا.اور کبھی اس کے معنے سواء کے بھی ہوتے ہیں.جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ یعنی سَوَآءُ ذَلِکَ نیز کبھی یہ ظرف مکان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.(اقرب) اَلصَّدِیْدُ.مَاءُالْجُـرْحِ الرَّقِیْقُ.اَلْمُخْتَلِطُ بِالدَّمِ قَبْلَ اَنْ تَغْلُظَ الْمِدَّةُ.پتلی خون آلود پیپ جو پیپ کے گاڑھا ہونے سے پہلے زخم سے نکلتی ہے.وَ قِیْلَ ھُوَ الْقَیْحُ الْمُخْتَلِطُ بِالدَّمِ اور بعض اس کے معنے صرف خون آلود پیپ کے کرتے ہیں.خواہ گاڑھی ہو خواہ پتلی.وَ قِیْلَ الْحَمِیْمُ اُغْلِیَ حَتّٰی خَثُرَ.اور بعض اس کے معنی گرم پانی کے بھی کرتے ہیں کہ جو ابل ابل کر گاڑھا ہو جائے.(اقرب) تفسیر.اس کے آگے جہنم ہو گی یعنی ایک لمبے عرصہ تک اس کا واسطہ جہنم سے پڑے گا.اور صدید یعنی گرم پانی پینے سے مراد گرم پانی بھی ہو سکتا ہے.کہ اس دنیا میں بھی گرم پانی سے علاج کیا جاتا ہے.گرم پانی پینے سے مراد ممکن ہے کہ جہنم میں بھی گرم پانی کی شکل میں کوئی روحانی علاج مقرر ہو.اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حصول مدعا کے ذرائع سامنے ہوںگے.لیکن انہیں استعمال نہیں کر سکیں گے.جس طرح تیز گرم پانی پانی تو ہے لیکن پیا نہیں جا سکتا.اس لئے پیاسے کو اسے دیکھ کر اور تکلیف پہنچتی ہے.زخموں کے دھوون سے مراد اگر زخموں کا دھوون سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی ان کے کاموں کا موجب ان کے ناپاک شہوات ہوتے تھے جو گویا اندرونی زخموں کا دھوون ہیں.کیونکہ شہوت قلب کی خرابی کا نتیجہ ہے.اگلے جہاں میں وہ ہی متمثل ہو کر زخموں کے دھوون کی شکل میں سامنے آئیں گے.دھوون کے معنی بھی علاج کو مدنظر رکھتے ہوئے چسپاں ہو سکتے ہیں.کیونکہ آج کل سب سے بہتر علاج ویکسین اور سیرم اور بیکٹروفیج ہیں.اور ان علاجوں میں بیماری کے ہی مختلف اجزاء اور کیڑوں کے لعابوں سے علاج کیا جاتا ہے.پس ہو سکتا ہے کہ علاج بالمثل کی طرف اشارہ ہو کہ ان کے گناہوں اور گندوں کے فاسد مادوں سے ہی ان کا علاج کیا جائے گا.یا یہ کہ ان کے گند ان کے سامنے رکھ دیئے جائیں گے جن سے ان کو گھن آئے گی اور اس طرح انہیں گند سے نفرت ہو جائے گی جیسا کہ سائکوانیلسس والے کرتے ہیں جو ایک نیا طریق علاج نکلا ہے.
Page 135
يَّتَجَرَّعُهٗ وَ لَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَ يَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ وہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے پیئے گا اور اسے آسانی سے نہیں نگل سکے گا اور ہر جگہ (اور ہر طرف) سے اس پر موت آئے مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ١ؕ وَ مِنْ وَّرَآىِٕهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ۰۰۱۸ گی اور وہ مرے گا نہیں اور اس کے علاوہ بھی( اس کے لئے )ایک سخت عذاب( مقرر) ہے.حلّ لُغَات.یَتَجَرَّعُہٗ.تَـجَرَّعَ سے مضارع کا صیغہ ہے.اور تَـجَرَّعَ الْمَاءَ کے معنے ہیں اِبْتَلَعَہٗ شَیْئًا بَعْدَ شَیْءٍ.اس کو تھوڑا تھوڑا کرکے حلق سے اتارا.وَمِنْہُ فِی الْقُرْاٰنِ.وَ يُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ.يَتَجَرَّعُهٗ اور آیت مذکورہ میں يَتَجَرَّعُهٗکے معنے یہی ہیں کہ اس کو گلے سے بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا کرکے اتارے گا.تَجَرَّعَ الْغَیْظَ کَظَمَہٗ غصہ کو دبایا.(اقرب) یَسِیْغُ اَسَاغَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور سَاغَ (جو اَسَاغَ کا مجرد ہے) کے معنے ہیں سَاغَ الشَّرَابُ فِی الْحَلْقِ.ھَنَا وَسَلِسَ وَسَہُلَ مَدْخَلُہٗ فِیْہِ کہ پانی راس آیا اور حلق سے بآسانی نیچے اتر گیا.(پس اَسَاغَ کے معنے ہوئے آسانی سے اتارا.لیکن کبھی اَسَاغَ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے جیسے) اَسَاغَ الطَّعَامُ اسَاغَۃً کے معنے ہیں سَہُلَ مَدْخَلُہٗ فِی الْحَلْقِ وَسَاغَ لَہٗ دَخُوْلُہٗ فِیہِ کھانا گلے میں آسانی سے اتر گیا.(اقرب) پس وَ لَا یَکَادُ یُسِیْغُہ کے معنے ہوں گے کہ اسے حلق سے آسانی سے نہیں اتار سکے گا.وہ اس کے لئے فائدہ مند ثابت نہ ہوگا.غَلِیْظٌ غَلِیْظٌ ذُوالْغِلَاظَۃِ.سختی والا.خِلَافُ الْلِّیْنِ وَالسَّلِسِ.نرمی اور سہولت کے مخالف معنے دیتا ہے.اَمْرٌغَلِیْظٌ شَدِیْدٌ صَعْبٌ.سخت مشکل امر.عَذَابٌ غَلِیْظٌ اَیْ شَدِیْدُ الْاَلَمِ.سخت دردناک عذاب.(اقرب) تفسیر.وَ يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اس سے بتایا ہے کہ جس طرح مومنوں کو جنت میں ہر دروازہ سے سلام آئے گا اسی طرح کفار کو ہر طرف موت کا سامنا ہوگا.یعنی قسم قسم کے گنہ جو وہ کرتے تھے موت کی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے.مگر فرمایا کہ وہ اس موت سے مریں گے نہیں کیونکہ اصل غرض ان کی اصلاح ہے.آخر سلامتی پہنچ جائے گی.کیونکہ انسان سلامتی کے لئے پیدا ہوا ہے.موت نہ پہنچے گی کیونکہ انسان موت کے لئے نہیں پیدا کیا گیا.(سوائے پہلی موت کے)
Page 136
جنت کے لئے باب اور دوزخ کے لئے مکان کا لفظ استعمال کرنے میں حکمت جنت اور دوزخ کے ذکر میں (جنت کا ذکر سورۂ رعد میں آیا تھا دیکھو آیت ۲۴،۲۵) ایک یہ فرق بھی رکھا ہے کہ جنت کے متعلق تو باب کا لفظ استعمال کیا تھا اور دوزخ کے لئے مکان کا.اس کی وجہ یہ ہے کہ سلامتی باہر سے آتی ہے یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے اور موت یعنی ہلاکت انسان اپنے لئےخود پیدا کرتا ہے.پس سلامتی کے لئے تو فرمایا کہ دروازوں سے آئے گی اور ہلاکت کے لئے فرمایا کہ اندر سے ہی ہر کونہ سے نکل پڑے گی.وَ مِنْ وَّرَآىِٕهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌسے مراد وَ مِنْ وَّرَآىِٕهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ سے یہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ اس عذاب کے بعد اور عذاب آئیں گے.مثلاً خدا تعالیٰ سے دوری، ندامت، حسرت وغیرہ اور یہ بھی کہ یہ عذاب ایک دفعہ مل کر ہٹ نہ جائے گا بلکہ لمبا چلتا جائے گا.مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ جن لوگوں نے اپنے رب (کے احکام) کا انکار کیا ہے ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے ایک تیز آندھی والے ا۟شْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ١ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ دن ہوا تیزی سے (اڑا) لے گئی ہو.جو کچھ انہوں نے( اپنے مستقبل کے لئے) کمایا ہے اس میں سے کوئی حصہ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ١ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ۰۰۱۹ (بھی) ان کے ہاتھ نہیں آئے گا یہی پرلے درجہ کی تباہی ہے.حلّ لُغَات.عَاصِفٌ.عَصَفَ سے اسم فاعل ہے اور عَصَفَ الزَّرْعَ یَعْصُفُ عَصْفًا کے معنے ہیں جَزَّہٗ قَبْلَ اَنْ یُّدْرِکَ کھیتی کو پکنے سے پہلے ہی کاٹ لیا.الرِّیْحُ تَعْصِفُ عَصْفًا وَعُصُوْفًا.اِشْتَدَّتْ.ہوا کے لئے جب عَصَفَ کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں ہوا تیزی سے چلی.عَصَفَ فُلَانٌ عِیَالَہٗ کَسَبَ لَھُمْ اپنے اہل و عیال کے لئے کمایا.عَصَفَ الْحَرْبُ بِالْقَوْمِ ذَھَبَتْ بِھِمْ وَاَھْلَکَتْہُمْ.لڑائی نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا.اور عَصَفَ الدَّھْرُ بِھِمْ بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا.النَّاقَۃُ بِرَاکِبِھَا کے معنے ہیں اَسْرَعَتِ السَّیْرَ کَاَنَّھَا الرِّیْـحُ.اونٹنی اپنے سوار کو تیزی سے لے کر چلی.گویا کہ وہ
Page 137
ہوا ہے.الشَّیْءُ مَالَ چیز کے متعلق آئے تو اس کے معنے جھکنے کے ہوتے ہیں.الرَّجُلُ اَسْرَعَ آدمی کے لئے یہ لفظ آئے تو اس کے معنے جلدی کرنے کے ہوتے ہیں.اور عَاصِفٌ کے معنے اَلْمَائِلُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ کے بھی ہوتے ہیں یعنی ہر چیز کا مائل حصہ.یَوْمٌ عَاصِفٌ کے معنے تَعْصِفُ فِیْہِ الرِّیْـحُ کے ہیں یعنی وہ دن جس میں ہوا بہت تیزی سے چلے اور یہاں اسم فاعل کا صیغہ بمعنی اسم مفعول استعال ہوا ہے اور اس کی جمع عَوَاصِفُ آتی ہے.(اقرب) تفسیر.كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْسے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور طاقتوں کا انکار ہے كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا.کیونکہ وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے.اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار یا اس کی طاقتوں کا انکار ہے.اللہ کی طاقتوں کے منکروں کو اعمال فائدہ نہیں دیتے بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن اس کا دخل دنیا میں نہیں مانتے.جیسے کہ اس زمانہ کے مغربی تعلیم پائے ہوئے لوگ ہیں.انہی سے ننانوے فی صدی بلکہ زیادہ اگر خدا تعالیٰ کو مانتے بھی ہوں تو بھی اس امر کو نہیں مانتے کہ وہ اس دنیا کے معاملات میں کوئی دخل دیتا ہے.اس لئے ان کے سب کام دنیا یا نفس کے لئے ہوتے ہیں.اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے یا اس کے خوف کے سبب سے نہیں ہوتے.ایسے لوگوں کی نسبت فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کوئی روحانی فائدہ نہیں دیتے.روحانیت یا آخرۃ کے لحاظ سے وہ ایسے ہی بیکار ہیں جیسے کہ وہ راکھ جس پر آندھیوں کے موسم میں تیز آندھی چلی ہو.جیسے متواتر اور شدید آندھی کے سبب سے اس راکھ کا نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہتا اسی طرح ان لوگوں کے اعمال آخرت کے لحاظ سے باطل ہوتے ہیں.دنیا کے لئے کئے ہوئے عمل کا فائدہ دنیا تک ہی محدود رہ سکتا ہے کیونکہ جو کام دنیا کے لئے کیا گیا ہو اس کا فائدہ دنیا تک ہی محدود رہ سکتا ہے اور یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے.کیونکہ عمل کا طبعی نتیجہ تو وہ ہے جو اس کے بعد قاعدہ کے طور پر مترتب ہوتا ہے.اور وہ نتیجہ کا فر و مومن ہر شخص کو مل جاتا ہے.جو شخص غریبوں کی خبرگیری کرتا ہے غربا اس کی خدمت کرتے اور بوقت ضرورت اس کے لئے جان تک دے دیتے ہیں.جو سچ بولتا ہے لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں اور ہزاروں مواقع پر اس اعتبار کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے.پس جب طبعی نتیجہ انسان کو مل گیا پھر اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا.خدا تعالیٰ کے لئے نیکی کرنے والے کو دگنا فائدہ لیکن جو شخص نیکی خدا تعالیٰ کے لئے کرتا ہے اس کے ظاہری عمل کے ساتھ ایک اور عمل اخلاص باللہ کا بھی شامل ہو جاتا ہے اور ظاہری نتیجہ کے نکلنے کے باوجود اس عمل کے
Page 138
صلہ کا وہ مستحق رہ جاتا ہے.اور اسی کو اخروی ثواب کہتے ہیں.یہ ثواب چونکہ عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ عمل کے ساتھ کے اخلاص باللہ کا نتیجہ ہوتا ہے.ظاہر ہے کہ اس کا مستحق وہی شخص ہوسکتا ہے جس کے اعمال اپنے ساتھ اِبْتِغَاءً لِوَجْہِ اللہِ کا عمل بھی رکھتے ہوں.یعنی نیک کام کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خواہش بھی شال ہو.اور جس کے عمل کے ساتھ یہ امر نہ ہو اس کا بس اتنا ہی بدلہ تھا جو اسے دنیا میں مل گیا.دوسرے معنے آیت کے یہ ہیں کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں کوششیں کرتے ہیں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی.بیکار ہوں گی.کیونکہ مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہے.تمام اسباب اسی نے پیدا کئے.پھر وہ ان اسباب کو کس طرح کامیاب کرسکتا ہے جو خود اس کے دین کے خلاف ہوں؟ عارضی خوشی منکران حق کو پہنچ سکتی ہے مگر اس امر کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عارضی خوشیاں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے دشمنوں کو بھی پہنچا دیتا ہے اور عارضی اور وقتی فتوحات انہیں بھی ملتی رہتی ہیں جن کا مقصد ایک تو نصرت الٰہی کو چمکا کر دکھانا ہوتا ہے دوسرے اس وقفہ سے نیک لوگوں کے لئے توبہ کا موقع بھی مہیا کیا جاتا ہے.ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ.یعنی اس سے زیادہ ہلاکت کیا ہوگی کہ انسان محنت کرے لیکن اس کا پورا فائدہ نہ اٹھائے.یا وہ محنت الٹی اس کے خلاف پڑے.اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ١ؕ اِنْ يَّشَاْ (اے مخاطب )کیا تو نےدیکھا نہیں کہ اللہ( تعالیٰ) نے آسمانوں اور زمین کو حق (و حکمت) کے ساتھ پیدا کیا ہے يُذْهِبْكُمْ وَ يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍۙ۰۰۲۰ اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اور( تمہاری جگہ پر) کوئی (اور) نئی مخلوق لے آئے.حلّ لُغَات.اِنْ يَّشَاْيُذْهِبْكُمْ اَلذِّھَابُ.الْمُضِیُّ.ذِھَابٌ کے معنے ہیں چلے جانا.وَقَالَ اِنْ یَّشَأْ یُذْھِبْکُمْ کِنَایَۃً عَنِ الْمَوْتِ.آیت اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ میں ہلاک کرنے کے معنے مراد ہیں یعنی اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے.(مفردات) تفسیر.اپنے عمل سے دنیا کی پیدائش کو بیکار کرنے والوں کی سزا یعنی دنیا کی پیدائش بیکار نہیں.پس ایسے لوگ جو اپنے عمل سے اسے بے کار بنارہے ہیں انہیں خدا تعالیٰ اس دنیا پر کب حکومت دے سکتا
Page 139
ہے.کیونکہ ان کا وجود تو پیدائش عالم کی غرض کو باطل کررہا ہے.پس انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خطرہ کے مقام میں ہیں.اور یہ بھی انہیں نہ سمجھنا چاہے کہ انہیں کوئی شخص اپنے مقام سے ہٹا نہیں سکتا کیونکہ ان کا کوئی قائم مقام نہیں ہوسکتا.خدا تعالیٰ ایسا کرسکتا ہے کہ انہیں ہلاک کرکے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ لے آئے.دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ لانے سے مراد نبیوں کی جماعتیں ہیں دوسرے لوگوں سے اس جگہ نبیوں کی جماعت مراد ہے.اور صرف یہ بتانا مقصود نہیں کہ وہ ایسا کرسکتا ہے بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا نہ سمجھیں کہ ان کا قائم مقام نہیں مل سکتا.ان کا بہتر قائم مقام تیار ہورہا ہے.وَّ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ۰۰۲۱ اوریہ بات اللہ( تعالیٰ) کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے.حل لغات.عَزیْز.یُقَالُ عَزَّ عَلَـیَّ کَذَا.اَیْ صَعُبَ.عَزَّ عَلَـیَّ کَذَا کے معنے ہیں کہ یہ کام مجھ پر مشکل ہو گیا.(مفردات) وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍکے معنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کوئی مشکل بات نہیں.تفسیر.دنیا میں کمزور اقوام کا ترقی کرنا اور زبردست کا زیر دست ہونا ناممکن امر نہیں دنیا کا عجب حال ہے.جب کوئی قوم کمزور ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ اب ہمارا بڑھنا ناممکن ہے اور جب کوئی قوم ترقی کر جاتی ہے تو کہتی ہے کہ اب ہمارا ہلاک ہونا ناممکن ہے.حالانکہ لوگ ہر زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ کمزور اقوام ترقی کر گئیں اور زبردست، زیردست ہو گئیں.اس آیت میں اسی غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے.ہزاروں دفعہ اللہ تعالیٰ نے گری ہوئی قوموں کو ترقی دی ہے اور ہزاروں دفعہ ترقی یافتہ قوموں کو قعرِمذلّت میں گرایا ہے.وَ بَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّا اور وہ سب اللہ (تعالیٰ) کے حضور آکھڑے ہوں گے تب (ان میں سے) کمزور( سمجھے جانے والے )ان سے جو كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ تکبر کیا کرتےتھے کہیں گے( کہ) ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے پس کیا تم اللہ( تعالیٰ) کے عذاب میں سے
Page 140
اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ١ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ١ؕ سَوَآءٌ (اس وقت) کچھ بھی ہم پر سے دور کر سکتے ہو.وہ( جواب میں) کہیں گے کہ اللہ (تعالیٰ )ہمیں ہدایت دیتا تو ہم عَلَيْنَاۤ اَجَزِعْنَاۤ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍؒ۰۰۲۲ ( بھی) تمہیں ہدایت دیتے (لیکن اب کیا ہو سکتا ہے) ہمارا بے صبری دکھانا یا ہمارا صبر کرنا( اس وقت) ہمارے لئے یکساں ہے (اور) ہمارے لئے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے.حلّ لُغَات.اَغْنٰی مُغْنُوْنَ.اَغْنٰی سے ہے اور اَغْنٰی عَنْہُ کے معنے ہیں اَجْزَأَہٗ.اس سے کفایت کی.اس کی تکلیف خود اٹھا کر اس کو بچا لیا.اور جب مَایُغْنِیْ عَنْکَ ھٰذَا بولا جائے تو اس سے یہ معنے مراد ہوتے ہیں مَایُجْدِیْکَ کہ یہ بات تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی.(اقرب) پس فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا کے معنے ہوں گے کہ کیا تم ہمارے عذاب اٹھا کر ہم کو عذاب سے بچا سکتے ہو.یا ہمیں کچھ فائدہ دے سکتے ہو.مَحِیْصٌ.حَاصَ یَـحِیْصُ کا مصدر ہے اور حَاصَ مَحِیْصًا کے معنے ہیں عَدَلَ وَحَادَ.بچاؤ کرکے ایک طرف ہو گیا.اَلْمَحِیْصُ.اَلْمَحِیْدُ.ایک طرف بچاؤ کی جگہ.بچاؤ اَلْمَھْرَبُ.بھاگنے کی جگہ (اقرب) مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ کے معنے ہوں گے ہمارے لئے بھاگنے کی کوئی صورت نہیں.کوئی بچاؤ کی صورت نہیں.تفسیر.آیت کے لفظ ماضی کے ہیں اور معنے مستقبل کے اس آیت میں ماضی کے صیغے استعمال کئے گئے ہیں لیکن ترجمہ مستقبل کا کیا گیا ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ گو لفظاً ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں لیکن مراد آئندہ زمانہ سے ہے کیونکہ یہاں ذکر عذاب کا ہے اور عذاب آئندہ آنے والا تھا.ابھی تک آیا نہ تھا.کسی امر کے یقینی وقوع پذیر ہونے کے لئے ماضی کے صیغے استعمال کئے جاتے ہیں ماضی کے صیغے اس امر پر زور دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے استعمال کئے ہیں کہ وہ دن ضرور آئے گااور یہ نظارہ ضرور دنیا کو دیکھنا پڑے گا.عربی کا محاورہ ہے کہ جب کسی مستقبل کے امر کے یقینی ہونے پر زور دینا ہو تو ماضی کے صیغے استعمال کئے جاتے ہیں.قرآن کریم میں اس کی مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں.اردو میں بھی اس قاعدہ کا وجود ملتا ہے.اگر کسی شخص کی آمد کی انتظار ہو اور کوئی شخص گھبراہٹ کا اظہار کرے تو منتظر شخص کے رشتہ دار یا دوست کہہ دیتے ہیں بس جی وہ آہی گیا ہے.یعنی اب اس کے آنے میںکوئی دیر نہیں اور اس کا آنا یقینی ہے.
Page 141
قومیں کمزوریوں کی وجہ سے اتنی ہلاک نہیں ہوتیں جتنی کمزوریاں ظاہر ہونےسے مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا منشاء تباہ کرنے کا ہوگا سب اس کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے.یعنی ان کی اندرونی کمزوریاں اورباطنی نقائص ظاہر ہونے لگیں گے.قوموں کی تباہی کے متعلق یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قومیں اس قدر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتیں جس قدر کہ ان کمزوریوں کے ظاہر ہونے کے سبب سے.جب تک ان کی کمزوریوں پر پردہ پڑا رہتا ہے باوجود کمزوریوں کی موجودگی کے وہ بڑھتی جاتی ہیں.کیونکہ لوگ ان سے مرعوب ہوتے ہیں.جب ان کی کمزوریاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر باوجود پورا زور لگانے کے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہیں.گویا کام اتنا کام نہیں آتا جس قدر کہ نام.اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عیب کو ظاہر کر دے گا.ورنہ خدا تعالیٰ تو ہر بات کو ہر وقت ہی جانتا ہے.قومی تباہی کا ایک سبب فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا یعنی جب قوم گرنے لگے گی تب کمزور طاقتوروں سے کہیں گے کہ اب ہماری حفاظت کرو.کہ ہم تو تمہارے پیچھے اور تمہارے کہنے پر چلتے تھے.مگر طاقتور کہیں گے کہ ہمیں خود کوئی راستہ نہیں ملتا.ساری تدبیریں بے کار جارہی ہیں.ہم تمہاری مدد کیا کریں.اس لئے صبر ہی کرو.اس میں پھر قومی تباہی کا ایک سبب بتایا ہے.جس قوم نے زندہ رہنا ہوتا ہے وہ گرتے گرتے بھی کوشش کو جاری رکھتی ہے.مگر جس قوم نے ہلاک ہونا ہوتا ہے وہ صبر کرکے خاموش ہو جانے کافیصلہ کرلیتی ہے.اور اپنی حالت پر راضی ہو جاتی ہے.حالانکہ صحیح صبر کا یہ مقام نہیں.صبر تو بری حالت سے بچنے کا نام ہے نہ کہ اس پر راضی ہو جانے کا.اس ا ٓیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ عذاب سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو جرم کی ترغیب دیتے رہتے ہیں.اور کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں ہم ذمہ دار ہیں.ہم تمہارے ساتھ ہیں.تو پھر تم کو کسی کا کیا ڈر.لیکن جب خدا کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا.یہی حال دنیوی جرائم کا ہے.بعض لوگ کسی کو قتل کا مرتکب بنا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم تمہیں بچائیں گے.لیکن جب وہ مجرم پکڑا جاتا ہے تو پھر بھلا کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے پکڑ لو.اس وقت کوئی اپنے آپ کو اس کی جگہ پیش نہیں کرتا.
Page 142
وَ قَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ اور جب تمام معاملہ کا فیصلہ کیا جا چکے گا تو شیطان( لوگوں سے) کہے گا (کہ) اللہ( تعالیٰ) نے یقیناً تم سے اٹل وعدہ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ۠١ؕ وَ مَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ کیا تھا.اور میں نے (بھی) تم سے (ایک) وعدہ کیا تھاپھرمیں نےوہ تم سے( کیا ہوا وعدہ) پورا نہ کیا اور میرا تم پر مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ١ۚ فَلَا کوئی تسلط نہ تھا ہاں میں نے تمہیں( اپنے خیالات کی طرف) بلایا اور تم نے میرا کہا مان لیا اس لئے (اب) تَلُوْمُوْنِيْ وَ لُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ١ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَاۤ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو (اس وقت) نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں اور اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ١ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ۠ مِنْ قَبْلُ١ؕ نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو.تم نے جو مجھے (اللہ تعالیٰ کاایک) شریک بنا رکھا تھا.میں( تمہاری) اس( بات) کا اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۰۰۲۳ پہلے سےانکار کر چکا ہوں (اس قسم کا شرک کرنے والے) ظالموںکے لئے یقیناً دردناک عذاب( مقدر) ہے.حلّ لُغَات.اَلْـحَقّ کے لئے دیکھیں حل لغات سورۃ رعد آیت نمبر۱۵.اَخْلَفْتُکُمْ: اَخْلَفَہٗ مَا وَعَدَہٗ کے معنے ہیں قَالَ شَیْئًا وَلَمْ یَفْعَلْہُ.کسی بات کے کرنے کا وعدہ کیا.اور پھر اسے پورا نہ کیا.فُلَانًا وَجَدَ مَوْعِدَہٗ خِلْفًا.اَخْلَفَ فُلَانًا کے معنے ہیں کہ اس کے وعدوں میں اختلاف پایا.(یعنی جھوٹے وعدے ہوتے ہیں.کبھی کچھ کبھی کچھ) اَخْلَفَ الْغَیْثُ.اَطْمَعَ فِی النُّزُوْلِ ثُمَّ نَقَصَ بارش پہلے اترتی ہوئی معلوم ہوئی پھر نہ اتری.اَخْلَفَ الدَّوَاءُ فُلَانًا اَضْعَفَہٗ.دوا نے کمزور کر دیا.(اقرب) پس اَخْلَفْتُکُمْ کے معنے ہوں گے کہ میں نے تم سے وعدہ کرکے اسے پورا نہ کیا (۲) میں نے تمہیں جھوٹے وعدے دے دے کر غافل رکھا اور کمزور کر دیا.
Page 143
اَلْمُصْرِخُ: اَصْرَخَ سے اسم فاعل ہے اور اَصْرَخَ فُلَانٌ کے معنے ہیں اَغَاثَہٗ وَاَعَانَہٗ.اس کی فریاد سنی اور اس کی مدد کی.اور جب یہ محاورہ بولیں اِسْتَصْرَخَنِیْ فَاَصْرَخْتُہٗ تو اس کے معنے ہوں گے اِسْتَغَاثَ بِیْ فَاَغِثْتُہٗ.کہ اس نے میری مدد چاہی.ا س پر میں نے اس کی مدد کی.اصرخ میں ھمزہ سبب کا بھی ہو سکتا ہے وَقِیْلَ الْھَمْزُۃُ لِلسَّلْبِ.بعض کہتے ہیں کہ اَصْرَخَ کا ہمزہ سلب کے لئے ہے اور اَصْرَخَ کے معنی ہیں ازلت صراخہ یعنی اس کی چیخ و پکار اور فریاد کو دور کر دیا.(اقرب ) اور چونکہ یہ مصیبت دور کرنے سے ہوتا ہے اس لئے اصرخ کے معنے مدد کرنے کے ہو گئے.پس آیت مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ کے معنے ہوں گے نہ میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کرسکتے ہو.(۲) نہ میں تمہاری چیخ و پکار کو دور کر سکتا ہوں نہ تم میری چیخ و پکار کو دور کرسکتے ہو.تفسیر.شیطان یا شیطانی لوگوں کا عذاب کے وقت اپنی براءت ظاہر کرنا شیطان یا شیطانی لوگ عذاب کے وقت اپنے آلۂ کار سے براءت ظاہر کرتے ہیں.اور کہتے ہیں کہ ہمارا تجھ پر کیا زور تھا.تمہارے اپنے اندر گند تھا.اس لئے تم نے ہماری بات مانی اگر تمہارے اندر نیکی ہوتی اور تم نہ مانتے تو ہم کیا تم کو مجبور کرسکتے تھے.اور یہ بات درست بھی ہے.اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان یا اس کے اظلال جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں انہیں انسان پر کوئی اختیار نہیں.وہ تو ایک ذریعہ ہیں انسانی کمزوری کے اظہار کا.جس طرح فرشتے ذریعہ ہیں اس کی اچھی طاقتوں کے اظہار کا.گمراہ کرنے والا خود انسان کا نفس ہے.فرشتے انسان کی نیکی کے معیار کو اور شیطان بدی کے معیار کو ظاہر کرتا ہے شیطان کا کام صرف اشارہ کرنا ہے.جیسے فرشتے نیکی کی طرف اشارہ کرتے ہیں.شیطان بدی کی طرف اشارہ کرتا ہے.اس کی مثال تو استاد کی سی ہے.کہ وہ شاگرد کے سامنے امتحان کےو قت مشکل سوال پیش کرتا ہے لیکن کوئی نہیں کہتا کہ استاد نے شاگرد کو فیل کیا.فیل تو طالب علم اپنی کمزوری کے سبب سے ہوتا ہے.استاد تو صرف اس کی لیاقت کے معیار کو ظاہر کرتا ہے.اسی طرح فرشتے انسان کی نیکی کے معیار کو اور شیطان بدی کے معیار کو ظاہر کرتے ہیں.نہ کہ نیک و بد بناتے ہیں.فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَ لُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ.یعنی تم نے ہمیشہ خدا تعالیٰ کے وعدے پورے ہوتے دیکھے.مگر انہیں قبول نہ کیا.میری طرف سے تمام جھوٹے ہی وعدے ہوئے اور تم نے ان کو مان لیا.تو بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟
Page 144
شیطان کا دعویٰ توحید اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ۠ مِنْ قَبْلُ.یہ لطیفہ ہے کہ شیطان توحید کا دعویدار ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے خدا تعالیٰ کا شریک بناتے تھے اور میں منکر تھا اور یہ ہے بھی درست.وہ شیطان جو انسانی کمزوریوں کو ظاہر کرنے پر مؤکل ہے وہ تو اپنا فرض ادا کررہا ہے اور خدا تعالیٰ کا جلال اس کے سامنے ہے.وہ شرک کس طرح کرسکتا ہے.شرک تو تب پیدا ہوتا ہے جب انسان شیطانی تحریک کو اپنے اندر لے کر اسے نافرمانی کی شکل میں ڈھال دیتا ہے.سنکھیا جب تک انسان کے پیٹ میں نہیں جاتا.ایک قیمتی دوا ہے جب انسان اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ زہر قاتل بن جاتا ہے.یہی مثال شیطان کی ہے.انسان کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ ایک امتحان کا سوال ہے اور کچھ بھی نہیں.شیطان کا دوزخ میں جانا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر شیطان دوزخ میں کیوں جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کی نسبت آتا ہے خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ.مجھے تو نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے) آگ سے پیدا کیا ہے.پس جو چیز آگ سے پیدا ہے آگ میں جانا اس کے لئے عذاب تو نہیں.ایک انگارہ کو اگر چولہے میں ڈال دو تو اسے کیا عذاب ہے.صوفیاء کا عام طور پر اسی طرف رجحان ہے کہ شیطان کے اظلال تو عذاب پائیں گے لیکن خود شیطان نہیں.کیونکہ وہ تو ایک امتحان لینے والی طاقت ہے اور فرض ادا کررہی ہے.وَ اُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے( نیک اور) مناسب حال عمل کئے ہوں گے انہیں ان کے رب کی مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ١ؕ تَحِيَّتُهُمْ اجازت سے ایسے باغوں میں جن کے( سایوں کے) نیچے نہریں بہتی ہوں گی داخل کیا جائے گا(اور) وہ اپنے رب فِيْهَا سَلٰمٌ۰۰۲۴ کی اجازت سے اس میں( ہمیشہ) بستے رہیں گے.اور ان (جنتوں) میں ان کی (ایک دوسرے کے لئے یہ) دعا ہو گی( تم پر) سلامتی (ہو).حل لغات.اَلْاذْنُ کے معنے ہیں اَلْاِجَازَۃُ.اجازت.اَلْاِرَادَۃُ.ارادہ.اَلْعِلْمُ.علم.(اقرب)
Page 146
اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ اے( مخاطب) کیا تو نے دیکھا نہیں (کہ) اللہ (تعالیٰ) نے کس طرح ایک پاک کلام کی حالت کو جو ایک پاک طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِۙ۰۰۲۵تُؤْتِيْاُكُلَهَا درخت کی طرح ہے (اور) جس کی جڑھ (مضبوطی کے ساتھ) قائم ہے اور اس کی( ہر ایک) شاخ آسمان( کی بلندی) كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا١ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ میں( پہنچی ہوئی) ہے کھول کر بیان کیا ہے.وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے اپنا (تازہ) پھل دیتا ہے اور لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۰۰۲۶ اللہ( تعالیٰ) لوگوں کے لئے (ان کی ضرورت کی) تمام باتیں بیان کر تاہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.حلّ لُغَات.ضَرَبَہٗ بِیَدِہٖ کے معنے ہیں اَصَابَہٗ وَصَدَمَہٗ بِھَا.اس کو ہاتھ سے مارا.ضَرَبَ بِالسَّوْطِ کے معنے ہیں جَلَدَہٗ.اس کو کوڑے سے مارا.(اقرب) اَلْمَثَلُ کے معنے ہیں اَلشِّبْہُ وَالنَّظِیْرُ.مشابہ.اَلصِّفَۃُ بیان.اَلـحُجَّۃُ.دلیل.یُقَالُ اَقَامَ لَہٗ مَثَلًا اَیْ حُـجَّۃً اَقَامَ لَہٗ مَثَلًا کہہ کر مثل سے مراد دلیل لیتے ہیں.اَلْحَدِیْثُ عام بات.اَلْقَوْلُ السَّائِرُ ضرب المثل.اَلْعِبْرَۃُ عبرت.اَلْاٰیَۃُ.نشان.(اقرب) اور ضَرَبَ لَہٗ مَثَلًا کے معنے ہیں وَصَفَہٗ وَقَالَہٗ وَبَیَّنَہٗ مثل کو بیان کیا.ا ور اچھی طرح سے واضح کیا.پس ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا کے معنے ہیں.کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے.طَیِّبَۃً.طَابَ میں سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور طَیِّبٌ کا مؤنث ہے.اور طَابَ الشَّیْءَ یَطِیْبُ طَابًا وَ طِیْبًا وَطِیْبَۃً وَطِبْیَانًا کے معنے ہیں لَذّ وَزَکٰی وَ حَسُنَ وَحَلَا وَجَلَّ وَجَادَ.کوئی چیز.لذیذ.پاکیزہ.خوبصورت.شیریں.شاندار.خوبیوں میں بڑھی ہوئی ہوگئی.اور طَابَتِ الْاَرْضُ کے معنی ہیں اَکْلَأَتْ زمین گھاس سے ہری بھری ہو گئی.طَابَتْ بِہِ نَّفْسِیْ اِنْبَسَطَتْ وَانْشَرحَتْ جی خوش ہو گیا.اور طَابَ الْعَیْشُ
Page 147
لِفُلَانٍ کے معنے ہیں فَارَقَتْہُ الْمَکَارِہُ.تکالیف دور ہو گئیں.طَابَتْ نَفْسِیْ عَلَیْہِ کے معنے ہیں وَافَقَھَا کہ میرے دل نے اس سے موافقت کی اور طَیّبٌ کے معنے ہیں ذُوالطّیْبَۃِ پاکیزگی والا.(اقرب) پس کَلِمَۃٌ طَیِّبَۃٌ کے معنے ہوں گے ایسا کلام جو اعلیٰ ہو.بڑھنے والا ہو.عمدہ ہو.خوشی پیدا کرنے والا ہو.فطرت انسانی کے موافق ہو.تفسیر.یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن کی تفسیر کرکے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہ صرف ان آیات کو حل کر دیا ہے بلکہ دوسری آیات کے لئے حل کرنے کا گر بھی ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے.مگر پیشتر اس کے کہ میں اس کی تفسیر کروں کَلِمَۃً طَیِّبَۃً کا اعراب بتا دینا چاہتا ہوں.کَلِمَۃً طَیِّبَۃً کی ترکیب کے متعلق نحویوں کااختلاف نحویوں نے کلمۃ کا اعراب دو طرح بیان کیا ہے.بعضوں نے کَلِمَۃً کو مَثَلًا کا بدل قرار دیا ہے.اس لحاظ سے ترجمہ یوں ہوگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ایک مثال یعنی کلمہ طیبہ کی.یہ معنے ابوالبقا نے کئے ہیں.ضَرَبَ مَثَلًا کے ساتھ استعمال ہو کر دومفعول چاہتا ہے ابن عطیّہ اور زمخشری کہتے ہیں کہ ضَرَبَ جب مَثَلًا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی جَعَلَ کی طرح دو مفعول چاہتا ہے.اس بناء پر انہوں نے کَلَمِۃً کو مفعول اوّل قرار دیا ہے اور مَثَلًا کو مفعول ثانی اور کَشَجَرَۃٍ کو مبتدا محذوف کی خبر بنایا ہے.یعنی ھی کَشَجَرَۃٍ طَیِّبَۃٍ تو ان کے نزدیک ترجمہ یہ ہوا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کلمہ طیبہ کو مثالی طور پر واضح کرکے بیان کیا ہے کہ وہ ایک شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑھ قائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں یا بلندی میں پھیلی ہوئی ہیں.کلمہ طیبہ سے مراد تازہ اور انسانی دستبرد سے پاک کلام ہے اب میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی حقیقت بیان کی ہے.یعنی اس کلام الٰہی کی جو تازہ اور پاکیزہ ہو اور انسانی دست برد سے پاک ہو اور اس کا موقع یہ تھا کہ پہلی آیات میں شیطانی راہوں پر چلنے والوں کے لئے تباہی کا ذکر فرمایا تھا اور ایمان لانے والوں کے لئے جنات اور انعامات کا.اس ذکر سے قدرتی طور پر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں وہ راہ اختیار کروں جو عذاب سے بچانے والی اور نعمتوں کا وارث بنانے والی ہو.لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے کہ اس سورۃ میں یہ ذکر موجود ہے کہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آئے ہیں.جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض نبی بعض کے کلام کو منسوخ کرنے والے تھے.تازہ اور مصفّٰی کلام الٰہی کے امتیاز کا معیار پس جب خدا تعالیٰ کا بعض کلام بعض دوسرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے تو انسان کس طرح معلوم کرے کہ فلاں خدائی کلام تو تازہ اور مصفیٰ ہے اور فلاں تازہ اور مصفیٰ نہیں؟ یا کس
Page 148
طرح معلوم کرے کہ فلاں تعلیم تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور دوسری نہیں.کوئی ایسا معیار چاہیے جس سے تازہ اور قابل عمل کلام دوسرے منسوخ شدہ کلام سے اور انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں سے ممتاز ثابت ہو.سو وہ معیار اس آیت میں بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعہ سے انسان بہ سہولت اس کلام الٰہی کی صداقت کو معلوم کر لیتا ہے.جو تازہ بتازہ اور اپنے زمانہ کے لئے قابل عمل ہوتا ہے.شجرۃ طیبہ اور کلمہ طیبہ کی پانچ علامات میں مشابہت فرماتا ہے کلمۃ طیّبۃ یعنی تازہ محفوظ اور نہ بگڑے ہوئے کلام الٰہی کی مثال شجرہ طیبہ کو سمجھ لو کہ (۱) وہ طیب ہو.یعنی ظاہری صورت اچھی ہو.(۲) اس کی جڑھ مضبوط گڑی ہوئی ہو.(۳) اس کی شاخیں آسمان میں پھیل رہی ہوں.(۴) اور وہ اپنا پھل ہر وقت دے رہا ہو.(۵) اور یہ پھل دینا اللہ تعالیٰ کے اذن کے ماتحت ہو.یہ پانچ علامات ہیں جو ایک تازہ اور ملاوٹ سے پاک کلام میں ہونی چاہئیں.اگر یہ علامات کسی کلام میں پائی جائیں تو وہ اس زمانہ کے لئے قابل عمل ہے اور اس زمانہ کے لوگوں کے لئے ہدایت نامہ ہے.لیکن اگر یہ اور کسی کتاب یا کلام الٰہی کہلانے والے صحیفہ میں نہ پائے جائیں تو وہ یا تو منسوخ شدہ کلام الٰہی ہے یا انسانی بناوٹ ہے.اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل نہیں ہے.اب میں الگ الگ سب علامتوں کو لیتا ہوں.کلام کے طیب ہونے کا مطلب پہلی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ طیب ہو.طیب کے معنے ہیں (ا) برائی عیب اور نقصان سے محفوظ شے.(ب) خوبصورت (ج) جو طیب والا ہو.اور طیب کے معنے ہیں (ا) لذیذ (۲) پاکیزہ (۳) خوبصورت (۴) شیریں (۵) شاندار (۶) خوبیوں میں بڑھا ہوا.پس خدا تعالیٰ کی طرف سے قابل عمل کلام وہ ہے جو اچھے درخت کی طرح ضرر اور نقصان سے محفوظ ہو.یعنی اس میں ایسی باتیں نہ ہوں جو انسانی روح یا انسانی شرافت یا انسانی احساسات و جذبات کے خلاف ہوں.دوسرے یہ کہ وہ خوبصورت ہو اور اس میں دلکشی اور جذب کے سامان ہوں.تیسرے اس پر عمل کرنے والا لذت اور سرور حاصل کرے.چوتھے اس میں حلاوت ہو.پانچویں وہ شاندار ہو.چھٹے وہ دوسروں سے خوبیوں میں بڑھا ہوا ہو.سچے کلام میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے اور انسانی فطرت کی سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے دوسری علامت یہ بتائی ہے کہ اس کی جڑھ مضبوط ہو.درخت کی جڑھ کے مضبوط ہونے سے ایک تو یہ مراد ہوتی ہے کہ درخت زندہ ہے اور زمین سے غذا لے رہا ہے.اسی طرح تازہ کلام الٰہی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی غذا لے رہا
Page 149
ہوتا ہے.جو کلام منسوخ ہو جاتا ہے اس کے مضامین کی وسعت ختم ہو جاتی ہے.کیونکہ وہ اس لئے منسوخ ہوتا ہے کہ اب وہ بنی نوع انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کرسکتا لیکن جو کلام قائم ہوتا ہے وہ انسانی فطرت کی سب ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور جو ضرورت بھی انسان کو پیش آئے جھٹ اس کلام سے اسے مل جاتی ہے.گویا وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جو زمین سے غذا لے رہا ہے اور اس سے تازہ مطالب جو زمانہ کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں ظاہر ہوتے رہتے ہیں.ا س میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مطالب اس میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں لیکن وقت پر ان کو ظاہر کرنا اور ضرورتوں کا اس سے پورا کرنا یہ خدا تعالیٰ کے تازہ فضل سے ہی ہوتا ہے.پس ایک رنگ میں یہ ہر وقت غذا لیتے رہنے کے مترادف ہے.سچا کلام اعتراضات سے متأثر نہیں ہوتا ۲- جڑھ کی مضبوطی سے ایک مراد اس کے تنے کی مضبوطی کے ہوتے ہیں.یعنی وہ صدمہ سے جھکتا نہیں.یہ بھی سچے کلام کی ایک علامت ہے کہ وہ اعتراضوں اور نکتہ چینیوں سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ جس قدر بھی اس پر بوجھ ڈالو وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور ہر قسم کے اعتراضوں کو اور جرح کو برداشت کر لیتا ہے.سچے کلام کے اصول پختہ اور غیر متبدل ہوتے ہیں ۳- تیسرے معنی جڑھ کی مضبوطی کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں.ان معنوں کی رو سے کلمہ طیبہ کی یہ علامت ہوگی کہ اس کے اصول ایسے پختہ ہوتے ہیں کہ زمانہ کے اختلاف سے بدلتے نہیں.زمانہ بدلتا جائے مگر اس کی تعلیم نہیں بدلتی.اور اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہتی ہے.جب بھی کسی کلام کو بدلنے کی ضرورت محسوس ہو سمجھ لو کہ اب وہ کلام خدا تعالیٰ کا تازہ کلام نہیں رہا.ایک سوکھا ہوا درخت ہے جس کی جڑھیں اکھڑ گئی ہیں.سچا کلام لمبی عمر پاتا ہے ۴- وہ لمبی عمر والا ہو.کیونکہ جن درختوں کی جڑھیں لمبی زمین میں جاتی ہیں وہ لمبی عمر پاتے ہیں.کلام الٰہی کی بھی یہ علامت ہے کہ وہ لمبی عمر والا ہوتا ہے.یہ نہیں کہ آج نازل ہوا اور کل منسوخ ہو گیا.کلام الٰہی سے مراد کلام الٰہی کا اصولی حصہ ہے ورنہ یہ ہوسکتا ہے کہ بعض جزوی امور ابتلاء اور آزمائش کی غرض سے بدلائے جائیں مگر یہ امور کبھی بھی اصولی تعلیم میں سے نہیں ہوتے.اصولی تعلیم کبھی جلد نہیں بدلتی.جیسے تورات کہ گو قرآن کریم نے اسے منسوخ کیا مگر یہ دوہزار سال بعد ہوا.درمیان میں نبی آتے رہے مگر ان کی بعثت کی غرض تورات کو منسوخ کرنا نہ تھی.سچے کلام پر عمل کرنےو الے مومنوں کی ایک جماعت موجود رہتی ہے ۵- اس کے ماننے والی اور
Page 150
اس پر عمل کرنے والی ایک جماعت ہو.جن کے اندر وہ پرورش پاکر بڑھے اور ترقی کرے کیونکہ جس طرح درخت زمین میں اپنی جڑھیں پکڑتا ہے کلام الٰہی مومنوں کے دلوں اور اعمال میں جڑھیں پکڑتا ہے.اگر اس پر عمل کرنیو الی کوئی جماعت نہ ہو تو اس کے آثار اور نتائج ظاہر نہیں ہوسکتے.پس مومنوں کی جماعت کلامِ الٰہی کے لئے بمنزلہ زمین ہوتی ہے اور اَصْلُهَا ثَابِتٌ کے یہ معنے ہیں کہ وہ ایمان لانے والوں کے قلوب پر ایک گہرا اثر ڈالتا ہے اور ان کے اندر مضبوطی سے جڑھیں پکڑ لیتا ہے.یعنی وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے کمالات کو ظاہر کرنے کا موجب ہوتے ہیں.۶- اس کا منبع ایک ہی ہوتا ہے.یعنی حیوان کی طرح اپنی غذا مختلف جگہوں سے نہیں لیتا بلکہ درخت کی طرح ایک ہی جگہ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے غذا لیتا ہے.مطلب یہ کہ انسانی کلام اور تعلیمات مختلف جگہوں سے خوشہ چینی کرتے ہیں.کچھ رسم و رواج سے لیا کچھ فلسفہ سے کچھ طبعیات سے کچھ رائج الوقت اصول سے اور اس وجہ سے ان تعلیمات میں باہمی اختلاف پایا جاتا ہے.اس کے برخلاف الٰہی کلام ایک ہی منبع سے نکلا ہوا ہوتا ہے.جڑھیں اس کی گہری ہوتی ہیں.یعنی ہر معاملہ پر سیرکن بحث کرتا ہے لیکن سب تعلیمات ایک ہی اصل کے ماتحت ہوتی ہیں.اور ان میں اختلاف نہیں ہوتا.ا ور نیز یہ کہ تازہ الٰہی کلام انسانی امداد کا محتاج نہیں ہوتا.سب غذا یعنی اس کی زندگی کا سامان جس سے مراد دلائل و براہین ہیں اپنی جڑھ سے ہی لیتا ہے.یعنی اللہ تعالیٰ سے جہاں سے وہ آیا ہے.آسمان میں شاخیں ہونے سے مراد تیسری علامت یہ بتائی تھی کہ اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں.اس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ۱- اس پر عمل کرکے انسان خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ جس درخت کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں جو شخص اس پر چڑھے گا لازماً آسمان تک پہنچ جائے گا.جو استعارۃً الہامی کتب میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا مقام قرار دیا گیا ہے.(۲) وہ تفصیلات شریعت کو مکمل طور پر بیان کرے.کیونکہ آسمان میں شاخوں کے پھیلنے سے شاخوں کی بہتات اور کثرت بھی مراد ہوسکتی ہے.پس کلام الٰہی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ معنے ہوں گے کہ اس کلام میں ہر انسانی ضرورت کے متعلق تعلیم موجود ہو اور اخلاقی اور مذہبی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جس پر اس میں بحث نہ ہو.گو اس نے روحانی آسمان کو اپنے پھیلاؤ سے ڈھانپ لیا ہو.سچے کلام کی تعلیم اعلیٰ اخلاق پر مبنی ہوتی ہے ۳- تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم اعلیٰ اخلاق پر مبنی ہو.کیونکہ اونچی شاخوں سے مراد ایک یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی تعلیم ادنیٰ اخلاق اور ادنیٰ امور پر
Page 151
مشتمل نہ ہو بلکہ اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم پر مشتمل ہو.سچے کلام سے ہر فطرت کے آدمی فائدہ اٹھاتے ہیں ۴- چوتھی بات فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر فطرت کے آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکیں.کیونکہ جس درخت کی شاخیں خوب پھیلی ہوئی ہوں اس کے سایہ کے نیچے بہت سے آدمی بیٹھ سکتے ہیں.پس اس میں کلام الٰہی کی اس صفت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کے سلسلہ میں بہت سے لوگ آسکتے ہیں.یعنی مختلف فطرتوں اور مزاجوں کے لوگوں کو وہ آرام دینے کا موجب ہوتا ہے.چوتھی علامت یہ بتائی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پھل دے رہا ہو.اس سے یہ مراد ہے کہ زندہ کلام الٰہی کی (۱) یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جو اس کے پھل کہلا سکتے ہیں یعنی وہ اس کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں.اور انہیں کلام کے اعلیٰ ہونے کی مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے.سچے کلام سے دائمی نجات حاصل ہوتی ہے ۲- دائمی نجات اس سے حاصل ہو.کیونکہ جس طرح تُؤْتِيْ اُكُلَهَا سے یہ مراد ہے کہ ہر وقت کامل انسان پیدا کرتار ہے اسی طرح یہ بھی کہ انسان ہمیشہ اس سے پھل کھاتا ہے اور ہمیشہ پھل تبھی کھا سکتا ہے جبکہ ہمیشہ کی پاکیزہ حیات انسان کو حاصل ہو.پانچویں علامت شجرہ طیبہ کی یہ بتائی کہ وہ اپنے پھل بِاِذْنِ رَبِّهَا دیتا ہے.یعنی اس کے اعلیٰ پھل طبعی نہیں ہوتے بلکہ اذن الٰہی سے ہوتے ہیں.کلام الٰہی کے درخت کو اس طرح عام درخت سے ممیز کر دیا گیا ہے.کیونکہ عام درخت قوانین طبعیہ کے ماتحت پھل دیتا ہے لیکن شجرہ طیبہ ایک ایسا درخت فرض کیا گیا ہے کہ جو پھل تو دے لیکن وہ پھل خاص حکم کے ماتحت ظاہر ہوں.ان کا ظہور الٰہی منشاء کے ماتحت ہو.اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کلام الٰہی کے نتائج صرف طبیعی نہیں ہوتے بلکہ شرعی بھی ہوتے ہیں.مثلاً سچ بولنا ہے اس کا ایک طبعی پھل ہوگا کہ لوگوں میں سچے آدمی کا وقار بڑھے گا لیکن اس کا ایک پھل شرعی ہوگا کہ ایسا انسان خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کا وارث ہوگا.نماز ہے.اس کا ایک ظاہری پھل تو یہ ہوگا کہ اطاعت اور نظام قومی کی تعلیم ہوگی لیکن ایک اس کا شرعی پھل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت ایسے شخص کو حاصل ہوگی اور وہ اس کا قرب پائے گا.قرآن مجید میں سچے کلام کی سب علامات پائی جاتی ہیں یہ علامات شجرہ طیبہ کی جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں تازہ کلام الٰہی کی جو مصفیٰ اور زندہ ہو ایسی بین تشریح کر دیتی ہیں کہ سچے اور جھوٹے کلام میں فرق کرنے میں کوئی مشکل ہی باقی نہیں رہتی.چنانچہ جب ہم ان علامات کی روشنی میں قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو ہر علامت اس میں ایسے حیرت انگیز طور پر پائی جاتی ہے کہ بلید سے بلید آدمی بھی اس امر کو تسلیم کرنے سے رک نہیں سکتا کہ یہ کلام اپنے
Page 152
اندر بے نظیر خوبیاں رکھتا ہے اور فوق العادت طاقتیں اس میں پائی جاتی ہیں.اس حد تک کہ نہ کوئی انسانی کلام اور نہ سابقہ آسمانی کتب اس سے ان امور میں برابری کرسکتی ہیں.ایک مختصر تفسیر میں ان امور کی تفصیلات بیان کرنے کا تو موقعہ نہیں مل سکتا لیکن اختصاراً میں ان امور کو قرآن کریم پر چسپاں کرکے بتاتا ہوں کہ یہ سب علامات قرآن کریم میں ایسے اعلیٰ اور اکمل طور پر پائی جاتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے.طیبہ کے لفظ میں خوبیوں کی طرف اشارہ سب سے پہلے میں ’’ طیبۃ‘‘ کے لفظ میں جن خوبیوں کی طرف اشارہ ہے انہیں لیتا ہوں.طیبۃ کا لفظ جس چیز کے لئے بولا جائے اس کے لئے شرط ہے کہ اس میں ظاہری یا باطنی کوئی نقص نہ ہو.کوئی ضرر نہ ہو.نازک ترین مضامین پر مشتمل ہونے کے باوجود قرآن مجید کی زبان نہایت اعلیٰ اور شستہ ہے اب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ بات غیر معمولی طور پر نظر آتی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس میں ایسے مضامین بیان کے گئے ہیں جو نہایت نازک ہیں لیکن پھر بھی اس کی زبان نہایت اعلیٰ اور تہذیب کے انتہائی نقطہ پر قائم رہتی ہے.میاں بیوی کے تعلقات حیض و نفاس کا ذکر،عورت و مرد کی جذباتی زندگی، یہ سب ہی کچھ اس میں بیان ہے.لیکن ایسے عمدہ طریق سے کہ نازک سے نازک طبیعت اس سے صدمہ محسوس نہیں کرتی.اس کی زبان ایسی صاف ہے کہ نہ ثقیل لفظ ہیں نہ پیچیدہ بندشیں، نہ شاعرانہ تخیلات بلکہ ہر مضمون کو خواہ کس قدر مشکل ہو وہ اس عمدگی سے اور ایسے سادہ لفظوں میں ادا کرتا ہے کہ نہ کانوں پر اس کی عبارت گران گزرتی ہے اور نہ دماغ اس سے پریشان ہوتا ہے.تعلیم ایسی سادہ اور لطیف ہے کہ اس پر عمل کرکے کسی نقصان کا خطرہ معلوم ہی نہیں ہوتا.قرآن مجید کا ظاہری حسن بے مثل ہے دوسرے معنے طیبۃ کے یہ ہیں کہ اس کا موصوف خوبصورت ہو.ان معنوں کی رو سے بھی قرآن کریم سب کتب سے ممتاز نظر آتا ہے.اس کا ظاہری حسن ایسا نمایاں ہے کہ کوئی کتاب اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتی.الفاظ کی خوبی، بندش کی چستی، محاورہ کا برمحل استعمال، عبارت کا تسلسل، مضمون کی رفعت، معانی کی وسعت، ایک سے ایک بڑھ کر خوبیاں ہیں.کہ انسان نہیں کہہ سکتا کہ اسے سراہے یا اس کی تعریف کرے.انہی عربی الفاظ سے وہ بنا ہے جو ہزاروں لاکھوں اور کتب میں استعمال ہوئے ہیں مگر کیا مجال کہ کوئی اور کتاب اس کے قریب تک پہنچ سکتی ہو.عرب اپنے خیالات کی نزاکت اور اپنے ادب کی بلندی اور اپنے ذخیرہ الفاظ کی کثرت کی وجہ سے سب دنیا کے لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں اور عرب قوم ادب کی اس قدر دل دادہ ہے کہ زور اور زر
Page 153
اور علو شان جیسی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی اشیاء بھی ان کے نزدیک ادب کے مقابلہ پر ہیچ ہیں.وہ اپنے شاعروں کو پیغمبراور اپنے ادیبوں کو دیوتا سمجھنے والے لوگ جن میں ادب اور ادیب کو ترقی کرنے کا بہترین موقعہ مل چکا تھا جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو زبانوں پر مہر لگ جاتی ہے.اور آنکھیں چندھیا جاتی ہیں.باوجود اس کے کہ نزول قرآن کریم کا زمانہ ان کا بہترین ادبی زمانہ تھا یا تو عرب کے چوٹی کے ادیب قریب میں ہی گزر چکے تھے یا ابھی زندہ موجود تھے.وہ جب قرآن کریم کو سنتے ہیں تو بے اختیار اس کے سحر ہونے کا شور مچا دیتے ہیں.مگر وہی لفظ جو اس کے جھوٹا ہونے کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اسی نے ظاہر کر دیا کہ عرب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ قرآن کریم کا حسن انسانی قوتِ تخلیق سے بالا تھا.انسانی دماغ نے بہتر سے بہتر ادبی مقالات بنائے تھے مگر اس جگہ اسے اپنے عجز کا اعتراف کئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا.فَسُبْحَانَ اللہِ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ.قرآنی مضامین کی وسعت بلندی اور تاثیر حیرت انگیز ہے اس کے مضامین کا بھی یہی حال ہے.ان کی بلندی ان کی وسعت، ان کی ہمہ گیری، ان کا نسانی دماغ کے گوشوں کو منور کر دینا، انسانی قلوب کی گہرائیوں میں داخل ہو جانا، نرمی پیدا کرنا تو اس قدر کہ فرعونیت کے ستونوں پر لرزہ طاری ہو جائے، جرأت پیدا کرنا تو اس حد تک کہ بنی اسرائیل کے قلوب بھی ابراہیمی ایمان محسوس کرنے لگیں.عفو کو بیان کرے تو اس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انگشت بدنداں ہو جائیں.سزا کی ضرورت کو ظاہر کرے تو اس طرح کہ موسیٰ ؑ کی روح بھی صلِ علیٰ کہہ اٹھے.غرض بغیر اس کے مضامین کی تفاصیل میں پڑنے کے ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں.ایک باغ ہے جس کے پھلوں کا خاتمہ نہیں.آج تک اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کلام بہت سے لوگوں نے مل کر بنایا ہے مگر کیا یہ خود اقرارِ حسن نہیں.قرآن مجید کی غیر معمولی لذت طَیّب کے تیسرے معنے لذت کے ہیں.قرآن کریم کی لذت کو دیکھو تو غیر معمولی ہے.ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو دیکھو وہ اپنے مذہب پر عمل کرکے بیزار نظر آتے ہیں لیکن قرآن کریم پر عمل کرنے والا کبھی اس سے بیزار نہیں ہوتا بلکہ زیادہ سے زیادہ مزہ اس سے اٹھاتا ہے.غرض اس میں کچھ ایسی لذت ہے کہ جو اس کا مزہ حقیقی طور پر چکھ لیتا ہے پھر اسے چھوڑنے کا نام نہیں لیتا.قرآن مجید میں پاکیزگی پر سب کتابوں سے زیادہ زور دیا گیا ہے طَیّب کے چوتھے معنے پاکیزگی اور نمو کے ہیں.قرآن کریم اس میں بھی بے مثل ہے.جس قدر پاکیزگی کی تعلیم پر قرآن کریم میں زور ہے اور کسی کتاب میں نہیں.ظاہری پاکیزگی کو دیکھو تو یہ قرآن کریم ہی ہے جو اسے مذہب کا جزو قرار دیتا ہے.قرآن کریم سے
Page 154
پہلے ظاہری صفائی اور روحانیت آپس میں مخالف چیزیں سمجھی جاتی تھیں.مسیحی راہب اپنی غلاظت پر فخر کرتے تھے.ہندو سادھو اپنی بھبوت اور چپکی ہوئی جٹاؤں پر نازاں تھے مگر قرآن کریم نے پاکیزگی کے اصول کو کیسا واضح کیا؟ اس نے کس طرح دنیا کی توجہ اس طرف پھیری کہ صاف جسم سے صاف روح پیدا ہوتی ہے.خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ طیبات کا استعمال روح کو گندہ نہیں بلکہ پاک کرتا ہے.اگر خدا تعالیٰ کا ولی ہی اس کی اچھی چیزوں کو پھینک دیتا ہے تو دوسرے ان کی صحیح قدر کو کب پہچان سکتے ہیں؟ ہاں! طیب چیزوں کو طیب صورت میں استعمال کرنا ضروری ہے.يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا (المؤمنون :۵۲) اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس کے نتیجہ میں نیک اور مناسب حال عمل کرو کہہ کر قرآن کریم نے جسم اور روح کے درمیان ایک ایسا رشتہ ظاہر کیا ہے کہ کتابوں کی جلدیں کی جلدیں اس کے بیان کرنے کے لئے ناکافی ہیں.قرآن کریم لذیذ ہونے کے علاوہ شیریں بھی ہے طیب کے پانچویں معنے شیرین کے ہیں.قرآن کریم نہ صرف لذیذ ہے بلکہ شیرین ہے.لذت صرف انسانی رغبت پر دلالت کرتی ہے مگر شیرینی اس کی مناسبت پر بھی دلالت کرتی ہے.قرآنی تعلیم میں کوئی تیزی نہیں، کوئی حدت نہیں.نازک سے نازک دماغ اس کو بلاتکلیف کے قبول کرتا اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے.قرآنی مضامین ایسے شاندار ہیں کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرسکتی چھٹے معنے طیب کے شاندار کے ہیں.قرآنی مضمون ایسے شاندار ہیں کہ کوئی کتاب اس میں ان کا مقابلہ نہیں کرسکتی.وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس طرح تفصیل سے بیان کرتا ہے وہ اس کی دنیا پر حکومت کو اس خوبی سے ظاہر کرتا ہے، وہ اس کے تصرف کو اس عمدگی سے ثابت کرتا ہے کہ قرآنی مضامین کو پڑھ کر انسانی روح وجد میں آجاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان سب دنیوی علائق کو توڑ کر آسمان کی طرف پرواز کرنے لگ گیا ہے.کون سی کتاب ہے جو اس امر میں اس کے سامنے آسکتی ہے.کون سا کلام ہے جو اس حسن میں اس کا مقابلہ کرسکتا ہے؟ قرآن کریم خوبیوں میں سب کتابوں سے آگے بڑھا ہوا ہے ساتویں معنے طیب کے خوبیوں میں بڑھے ہوئے ہونے کے ہیں.اوپر کے مطالب سے ہر شخص معلوم کرسکتا ہے کہ قرآن کریم ہر کتاب پر خواہ وہ الہامی ہو خواہ انسانی اس قدر فوقیت رکھتا ہے کہ وہ کتب کسی اور عالم کی معلوم ہوتی ہیں اور قرآن کریم کسی اور عالم کا.دوسری علامت کَلِمَۃٌ طَیِّبَۃٌ کی یہ بتائی گئی تھی کہ اَصْلُهَا ثَابِتٌ اس کی جڑھ مضبوط ہے اور اس علامت کی تشریح میں میں نے چھ باتیں بتائی تھیں.جن کو اگر قرآن کریم کے متعلق دیکھا جائے تو وہ سب کی سب اس میں
Page 155
بدرجۂ اتم پائی جاتی ہیں.قرآن مجید کے زندہ کتاب ہونے سے اس کے نئے نئے مطالب نکلتے رہتے ہیں اول قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے یعنی جس طرح زندہ درخت جس کی جڑھیں زمین میں پھیل کر ہر وقت غذا لے رہی ہوتی ہیں تازہ رہتا ہے.اسی طرح قرآن کریم کی تازگی قائم ہے.اور ہر وقت تازہ معانی اس سے ملتے ہیں.تیرہ سو سال سے لوگ اس کی تفاسیر لکھتے چلے آئے ہیں اور بعض نے تو سو سو جلدوں کی تفسیریں لکھی ہیں مگر باوجود اس کے اس کے مطالب ختم نہیں ہوئے.اب بھی اس میں سے نئے مطالب نکل رہے ہیں.اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک نلکی ہے جس کے ایک طرف بیٹھا ہوا کوئی شخص دوسری طرف خزانہ لڑھکا رہا ہے.کتنا ہی غور کرو کوئی سا سوال کرو.نئے مطالب کھلتے جاتے ہیں اور ہر سوال کا جواب ملتا جاتا ہے.قرآن کریم خود فرماتا ہے وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ١ۖۚ وَ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ.ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں سے کیا کیا شبہات پیدا ہوتے ہیں.اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں.(قٓ :۱۷) الٰہی کلام جب تک دنیا کے لئے قابل عمل ہے ایک تازہ درخت کی طرح ہونا چاہیے.یعنی وہ ہر وقت اپنے منبع سے غذا حاصل کررہا ہو.جس طرح درخت بظاہر وہی نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر تازہ رس حیات کا زمین سے آتا رہتا ہے.اسی طرح کلام وہی رہتا ہے لیکن اس کے تازہ مطالب حسب ضرورت کھلتے رہتے ہیں.اور ان کی طرف ذہن کا پھرانا اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں رکھتا ہے.اسی کی طرف اشارہ ہے لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۠ یعنی اس کلام کو سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے.(الواقعہ :۸۰) قرآن کریم میں ہر زمانہ کے اعتراضوں کا جواب موجود ہے مضبوط جڑھوں والے درخت کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صدمات سے جھکتا نہیں حوادث کا مقابلہ مضبوطی سے کرتا ہے.کلام وہی مضبوط جڑھ والا کہلا سکتا ہے جو ہر زمانہ کے اعتراضوں کی برداشت کرسکے.اور ان کا جواب اس کے اندر موجود ہو.قرآن کریم میں یہ خوبی بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے.اس کے اصول ایسے واضح ہیں کہ اس کے جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوسکتا.نہ اسے بدلانے کی کسی کو اجازت ہے.اور نہ خود اس کے اپنے الفاظ اس کے معانی کو بدلنے کی اجازت دیتے ہیں.اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کرنے والا قرآن کریم کو توڑ دے گا.مروڑ نہیں سکے گا.جس طرح عمارت میں سے چند اینٹیں نکال لی جائیں تو وہ گر جاتی ہے اسی طرح اس کی تعلیم کو کوئی بدلنا چاہے تو وہ سب کی سب ناقص ہو جائے گی.اسی طرح روحانی طور پر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو کوئی اختیار کرے اور بعض کو چھوڑ دے.
Page 156
یا سب کو چھوڑے گا یا سب کو اختیار کرے گا.ورنہ کوئی فائدہ نہ اٹھائے گا.چنانچہ اس وقت مسلمان بعض قرآن پر عمل کررہے ہیں اور بعض کو چھوڑ رہے ہیں.لیکن اس سے انہیں فائدہ کوئی نہیں پہنچ رہا.بلکہ غیرمسلم ان سے زیادہ ترقی کررہے ہیں.اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم دب کر نہیں رہنا چاہتا.جو اسے دبانے کی کوشش کرے وہ نقصان اٹھائے گا.ہاں! اسے بالکل چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیارکرلے.گویا قرآن کریم کی جڑھ کو اپنے دل سے اکھاڑ پھینکے تو پھر بے شک وہ دنیوی طور پر ترقی کرسکے گا.اسی طرح یہ امر بھی ثابت ہے کہ قرآن کریم تبدیلی زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا.کوئی علم نکلے کوئی ایجاد ہو اس کی تعلیم پر کوئی حملہ نہیں ہوسکتا.قرآن کریم کے اصول پختہ اور غیر متبدل ہیں تیسری خصوصیت مضبوط جڑھ والے درخت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑتا نہیں.یہ معنے بھی قرآن کریم میں بدرجہ اعلیٰ پائے جاتے ہیں.قرآن کریم کے اصول ایسے پختہ ہیں کہ وہ کبھی بدلتے نہیں.یہ نہیں کہ تعلیم کا ایک حصہ اور اصول پر مبنی ہو اور دوسرا حصہ دوسرے اصول پر.جیسے انجیل میں توحید اور تثلیث یا کفارہ اور رحم متضاد اصول پر مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے.آریہ مذہب میں ایک طرف خدا تعالیٰ کو دیالو کرپالو کہا گیا ہے تو دوسری طرف روح اور مادہ کو انادی.حالانکہ یہ دونوں تعلیمیں متضاد اصول پر قائم ہیں.لیکن قرآن کریم کی سب تعلیم مقررہ اصول پر قائم ہے.توحید ہے تو اس کے باریک سے باریک احکام اسی کے گرد چکر کھاتے ہیں.اللہ تعالیٰ کو رحمٰن اور رحیم قرار دیا گیا ہے تو تمام تفصیلی تعلیمات ان صفات کے تابع ہیں.یہ نہیں کہ توحید کی تعلیم دی ہو اور تفصیلات شرک پر مبنی ہوں.رحیم قرار دیا ہو اور جزئیات عدم رحم پر دلالت کرتی ہوں.قرآنی تعلیم تا قیامت قابل عمل رہےگی چوتھی خصوصیت مضبوط جڑھ کے درخت کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو.جس قدر جڑھیں مضبوط ہوں درخت لمبی عمر پاتا ہے.قرآن کریم پر تیرہ سو سال گزر چکے ہیں.اب تک اس کی تعلیم قابل عمل ہے اور قابل عمل رہے گی.جو کتب خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتیں وہ آج لکھی جاتی ہیں.اور کل ان کے خلاف انہی کے ماننے والے کہنے لگتے ہیں اور اس پر سے عمل اٹھ جاتا ہے لیکن قرآن کریم پر برابر عمل ہورہا ہے.بلکہ جو لوگ اسے چھوڑ رہے تھے اب پھر اس کی تعلیم کی طرف واپس آرہے ہیں.یورپین تہذیب کے دلدادہ قرآن کریم کی تعلیم کی خوبی کے قائل ہو رہے ہیں یورپین تہذیب کے دل دادہ اب پھر اس کی ظاہری خوبصورتی کا تلخ تجربہ کر لینے کے بعد دوبارہ قرآن کریم کی ٹھوس تعلیم کی خوبی کے قائل ہو رہے ہیں.سؤر کی حرمت، شرا ب کی ممانعت، کثرت ازدواج کی اجازت، طلاق، عورت اور مرد کے اختلاط میں
Page 157
حزم و احتیاط، ورثہ وغیرہ بیسیوں امور ہیں کہ جن میں قرآنی اصول کی برتری کو دنیا پھر تسلیم کرنے پر مجبور ہورہی ہے.اور اس طرح قرآن کی عمر جو ہمارے نزدیک تو تاقیامت ہے دشمنوں کے نزدیک بھی لمبی ہوتی نظر آتی ہے.پانچویں خصوصیت مضبوط جڑھوں والے درخت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھی مٹی میں اگتا ہے.یعنی ایسا درخت کبھی معمولی زمین میں نہیں اگ سکتا.کیونکہ جب تک جڑھوں کے پھیلنے کے لئے عمدہ مٹی دور تک نہ ملتی ہو جڑھیں دور تک پھیل نہیں سکتیں.اسی طرح کلام الٰہی بھی اپنے حسن کو تبھی ظاہر کرسکتا ہے جب ایسی قوم اس کی حامل ہو.جو اس سے مناسبت رکھتی ہو.اور اسے اپنے دلوں میں جگہ دینے کو تیار ہو.اسی کی طرف قرآن کریم میں یہ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے کہ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ (الفاطر :۱۱) عمل صالح ایمان کو ترقی دیتا ہے.یعنی درخت تو ایمان ہے لیکن وہ عمل صالح کے بغیر بڑھتا نہیں.پس گو کلام الٰہی کیسا اعلیٰ ہو جب تک اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو اس کی خوبی ظاہر نہیں ہوتی.پس ضروری ہے کہ کلام الٰہی ایسے دلوں میں جگہ پکڑلے جو اس کی تعلیم کے نشوونما کے لئے موزوں ہوں اور جن میں دور دور تک اس کی جڑھیں پھیل سکیں.جب تک یہ بات کسی کلام کو میسر نہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتا.قرآن کریم کو یہ بات بدرجہ اتم حاصل ہے.جب یہ ظاہر ہوا تب بھی ایک ایسی جماعت اسے میسر ہوئی جنہوں نے اس کا درخت اپنے دلوں میں لگایا.اور اپنے خون سے اس کی آبیاری کی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ بات اسے میسر ہے.وید، تورات، انجیل، سب کتب پر ایک وقت میں لوگ عمل کرتے تھے مگر آج ان پر عمل کرنے والے تلاش کرنے سے بھی شاید ہی ملیں.قرآن کریم پر عمل کرنے والے لوگ ہر زمانہ میں ملتے رہے ہیں لیکن قرآن کریم پر عمل کرنے والے لوگ ہر زمانہ میں ملتے رہے ہیں.اور جب بھی ان لوگوں میں کمی آتی رہی ہے اللہ تعالیٰ اور لوگ پیدا کر دیتا رہا ہے جو اس پر عمل کرنے والے تھے اور اس طرح اس کی جڑھیں مضبوطی سے گڑی رہی ہیں اور اس کا حسن ہمیشہ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہا ہے.باقی کتب میں اگر حسن بھی ہے تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی درخت کے حسن کو اس کا بیج ہتھیلی پر رکھ کر بیان کیا جائے اور قرآن کریم کا حسن اس کے خوبصورت درخت سے جو ہر وقت اگا ہوا ہے دکھایا جاسکتاہے اور قیاس سے حسن معلوم کرنا اور آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کرنا برابر نہیں ہوسکتا.انسانی کتب کے بالمقابل قرآن کریم کی تعلیم سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے چھٹی خصوصیت مضبوط جڑھوں والے درخت کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا منبع ایک ہوتا ہے.یعنی وہ حیوان کی طرح مختلف جگہ سے غذا نہیں لیتا.اس خصوصیت میں بے شک کمزور درخت بھی شامل ہے لیکن یہ مقابلہ حیوانات سے ہے.نہ کہ
Page 158
دوسرے درختوں سے.گویا دوسری الہامی کتب خواہ وہ قرآن کریم کی طرح شاندار نہ ہوں اس امر میں ایک حد تک اس سے مشابہ ہوں گی لیکن انسانی کلام نہیں.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سےہے.انسانی ہاتھ کا اس میں دخل نہیں.اس نے آہستہ آہستہ نشوونما حاصل نہیں کیا.بلکہ یکدم ایک ہی شخص کے دل پر اسے نازل کیا گیا ہے.وہ زمانہ کی رو کی ترجمانی نہیں کرتی کہ اسے صدیوں کے فلسفہ کا خلاصہ کہا جائے.جیسا کہ اچھی انسانی کتب کا حال ہے بلکہ وہ اکثر امور میںزمانہ کی رو کا مقابلہ کرتی اور ان کے خلاف چلتی ہے.اور اپنے لئے ایک بالکل نیا راستہ بناتی ہے.جس سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ اپنی غذا ایک ہی جگہ سے لیتی ہے اور درخت سے مشابہ ہے.برخلاف انسانی کتب کے کہ وہ حیوان کے مشابہ ہوتی ہیں.اور انتخاب اور استفادہ اور تجسس پر ان کی بنیاد ہوتی ہے.اور گو مصنف ایک نظر آتا ہے لیکن اس کا علم ماخوذ ہوتا ہے.ہزاروں انسانوں کے تجربہ سے.سوائے ان لوگوں کے کہ جو قرآن کریم پر اپنی تصنیفات کی بنیاد رکھتے ہیں.ان لوگوں کی تصنیفات قرآن کریم کا عکس ہیں.اس سے جدا نہیں.تیسری علامت شَجَرَۃٌ طَیِّبَۃٌ کی یہ بیان فرمائی تھی کہ فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں.آسمان میں شاخیں پھیلنے کے سات معنے میں نے اوپر بیان کئے ہیں اور ان معانی کے رو سے بھی قرآن کریم ایک ممتاز کتاب نظر آتی ہے.اس کے اس امتیاز میں کوئی اس کا شریک نظر نہیں آتا.قرآنی تعلیم پر عمل کرنے سے قرب الٰہی حاصل ہو جاتا ہے پہلی خصوصیت فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ کی میں نے یہ بتائی تھی کہ اس پر چڑھ کر انسان آسمان تک پہنچ سکے گا.یہ خصوصیت قرآن کریم میں واضح طور پر پائی جاتی ہے.بلکہ اس میں اس کے ساتھ کوئی اور کتاب شریک ہی نہیں.کیونکہ کوئی کتاب اس کی دعویٰ دار نہیں کہ اس پر عمل کرکے انسان خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے.لیکن قرآن کریم اس کا مدعی ہے کہ اس کی تعلیم پر عمل کرکے انسان آسمان پر پہنچ جاتا ہے.یعنی قرب الٰہی اسے حاصل ہو جاتا ہے.اور وہ آسمانی امور کو بچشم خود دیکھ لیتا ہے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے عاملین میں سے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو اس امر کے مدعی تھے کہ قرآن کریم کے ذریعہ سے انہیں روحانی صعود حاصل ہوا.یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ تک جا پہنچے.اور اس کے خاص فضلوں کو انہوں نے حاصل کیا.قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم ہر طبقہ کے لوگوں کے لئے ہے دوسری خصوصیت فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ کلام الٰہی کی تعلیم اعلیٰ اخلاق پر مشتمل ہوتی ہے.کیونکہ اونچا درخت بلند خیالی اور وسعت اخلاق پر
Page 159
بھی دلالت کرتا ہے.یہ امر بھی قرآن کریم میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے.قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم ایسی اعلیٰ ہے اور درخت کی شاخ کی طرح اس طرح ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف گئی ہے کہ کسی اور کتا ب میں اس کی نظیر نہیں ملتی.بعض کی اخلاقی تعلیم نہایت ادنیٰ ہے جس طرح زمین پر گری ہوئی شاخ.اور بعض کی اعلیٰ تو ہے لیکن اس کا جڑھ سے تعلق نہیں.وہ ایسی ہے جیسے کسی تاگا سے کسی شاخ کو بلندی میں لٹکا دیں.وہ بلند تو ہو جائے گی لیکن اس پر کوئی چڑھ نہیں سکے گا.لیکن قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم ایسی ہے جس پر ہر طبقہ کا آدمی عمل کرسکتا ہے.ادنیٰ آدمی جڑھ سے چڑھ کر اوپر جاسکتا ہے اور اوپر پہنچا ہوا آدمی اس کے اوپر اور ترقی کرسکتا ہے.اس کی اس خوبی پر بعض لوگ معترض ہوتے ہیں.مثلاً سزا کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح ادنیٰ اخلاق سکھائے گئے ہیں.حالانکہ نہیں دیکھتے کہ ادنیٰ اخلاق والے انسانوں کی اصلاح اس کے بغیر نہیں ہوسکتی.کچھ لوگ سزا سے مانتے ہیں، کچھ عفو سے، پھر کچھ عدل کے مقام پر ہوتے ہیں، کچھ احسان کے اور کچھ ایتاء ذی القربیٰ کے.جو مذہب ان امور کو اپنی تعلیم میں شامل نہیں کرتا وہ لوگوں کو یا اعلیٰ اخلاق سے محروم کر دیتا ہے یا انسانوں میں سے ایک حصہ کو نجات سے محروم کر دیتا ہے.غرض اس خصوصیت میں بھی قرآن کریم ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے.قرآن کریم کی تعلیم اس قدر مطالب پر حاوی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے تیسری خصوصیت فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ کے ماتحت یہ ہے کہ اس کی شاخیں بہت ہوں.کیونکہ جس درخت کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں گی وہ نہ صرف اونچی ہوں گی بلکہ بہت کثرت سے بھی ہوں گی.(یاد رہے کہ اِلَی السَّمَآءِ نہیں فرمایا فِي السَّمَآءِ فرمایا ہے جس سے بلندی کے علاوہ پھیلاؤ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے) اس خصوصیت میں بھی قرآن کریم کو ایک ممتاز درجہ حاصل ہے.اس کی تعلیم اس قدر مطالب پر حاوی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے.ایک مختصر سی کتاب ہے.اناجیل سے بھی چھوٹی.لیکن اس کے اندر اس قدر مطالب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اس سے ہزاروں گنے زیادہ حجم کی کتب میں وہ مضامین نہیں ملتے.عبادات ہیں تو ان کی ہر شاخ اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے.معاملات ہیں تو ان کی ہر شاخ اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے.علم الاخلاق، تمدن، سیاست، اقتصادیات، پیشگوئیاں، الٰہیات، قضاء، تصوف،علم المعاد، علم کلام اور ان سب علوم کے فلسفے اور تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں.اور ایسے کامل طور پر موجود ہیں کہ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی.(اس کے لئے دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی اور آئینہ کمالات اسلام اور میری کتاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام وغیرہ)
Page 160
ہر فطرت کے انسان کے لئے قرآن کریم میں تسلی کا سامان ہے چوتھی خصوصیت فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ کے ماتحت یہ ہے کہ اس کا سایہ وسیع ہو.کیونکہ جس درخت کی شاخیں بلند اور پھیلی ہوئی ہوں اس کا سایہ بھی بہت وسیع ہوتا ہے.پس کلمہ طیبہ وہ ہے جس کے سایہ میں بہت سے آدمی بیٹھ سکیں.یعنی وہ ہر فطرت کے انسانوں کے لئے تسلی دینے کا موجب ہو.یعنی جس طرح اخلاق کے ہر درجہ کے لوگوں کو بلندی کی طرف پہنچائے.اسی طرح ہر فطرت کے انسان کے لئے بھی اس میں تسلی کا سامان موجود ہو.قرآن کریم میں یہ صفت بھی بدرجہ اتم موجود ہے.انسانی مزاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں.کوئی انسان کسی طاقت اور میلان کو لے کر آتا ہے کوئی کسی طاقت اور میلان کو.کامل کتاب میں سب کے لئے آرام کا سامان موجود ہونا چاہیے اور قرآن کریم میں ایسا ہی ہے.کسی طبعی تقاضے کو ضائع نہیں کیا گیا.کچلا نہیں گیا.باقی تمام مذاہب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بشریت کے تقاضوں کو گناہ قرار دے کر ان کے کچلنے پر سارا زور لگایا گیا ہے.قرآن کریم بشری تقاضوں کو انسانی تکمیل کے ذرائع قرار دے کر ان کی اصلاح پر زور دیتا ہے لیکن قرآن کریم نے بشریت کے تقاضوں کو انسانی تکمیل کے ذرائع قرا دے کر ان کی اصلاح پر زور دیا ہے.جس طرح گاڑی چلانے کے لئے نہ جانور کو ذبح کرنے والا کامیاب ہوسکتا ہے نہ اسے آزاد چھوڑ دینے والا.بلکہ وہی کامیاب ہوسکتا ہے جو بیلوں اور گھوڑوں کو سدھا کر اس کے آگے جوتے.قرآن کریم بھی بشری تقاضوں کو سدھا کر ہر فطرت کے انسان کے لئے آرام کا سامان پیدا کرتا ہے.وہ نرم مزاج انسان کو نرمی سے روکتا نہیں نہ سخت مزاج کو سختی سے.بلکہ انہیں اپنے طبعی تقاضے کے صحیح موقع پر استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے.وہ نہ تو کھانے کو گناہ قرار دیتا ہے نہ پہننے کو نہ شادی کو نہ مال و دولت کمانے کو نہ مکان بنانے کو بلکہ ہر امر میں اقتصاد اور مناسب حدود کو قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے.اس وجہ سے ہر فطرۃ کی اصلاح اس کے ذریعہ سے ہو جاتی ہے.اور کوئی شخص نہیں جو اس کے سایہ میں بیٹھ نہ سکے.چوتھی علامت شَجَرَۃٌ طَیِّبَۃٌکی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ ہر آن اپنے پھل دیتا ہے.اس علامت کے ماتحت کلام الٰہی کی ایک تو یہ خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ پھل دیتا رہے یعنی اس میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں جو اس کی اعلیٰ تعلیم کے مظہر ہوں.اس لئے تُؤْتِي الْاُكُلْ نہیں فرمایا بلکہ اُکُلُھَا فرمایا.یعنی درخت کی طرف ضمیر پھیر کر اس کی خوبیوں کی طرف اشارہ کیا.کہ وہ پھل اپنے اندر درخت والی خوبیاں رکھتے ہوں.جو خواص اس درخت میں ہوں وہی ان پھلوں میں ہوں.وہ طیب بھی ہوں وہ مضبوط جڑھ پیدا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں.اور
Page 161
آسمان میں پھیل جانے کی طاقت بھی.یہ خاصیت بھی قرآن کریم میں پائی جاتی ہے بلکہ اس وقت صرف اس میں پائی جاتی ہے.یعنی اس پر عمل کرنے والے لوگ اس کے ذریعہ سے ایسے اعلیٰ مقامات تک پہنچتے ہیں کہ گویا وہ مجسم قرآن ہو جاتے ہیں.اسی کی طرف اشارہ ہے.کَانَ خُلُقُہُ الْقُرْاٰنُ میں (مجمع البحار) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر دیکھنا چاہو تو قرآن کریم دیکھ لو.جو تعلیمات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور جو اعلیٰ صفات اس میں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے.مَا اَنَا اِلَّا کَالْقُرْاٰنِ سَیَظْھَرُ عَلٰی یَدِیْ مَاظَھَرَ مِنَ الْفُرْقَانِ کے الہام میں جو اس زمانہ کے قرآنی پھل حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام پر ہوا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں قرآن کی طرح ہوں اور جو کچھ اس سے ظاہر ہوا مجھ سے بھی ظاہر ہوگا(الحکم ۲۴ ؍ستمبر ۱۹۰۶ءصفحہ ۱).یعنی تعلیم قرآنی میرے وجود میں دنیا کو نظر آئے گی.اس الہام میں گویا تُؤْتِيْاُكُلَهَاکا مصداق ہونے کی طرف اشارہ ہے.قرآن کریم دائمی نجات دیتا ہے دوسری خصوصیت تُؤْتِيْاُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ کے ماتحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ دائمی نجات دے اور یہ مفہوم اس سے پیدا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں کلام الٰہی داخل ہو کر ایک درخت بنے گا اگر وہ شخص دائمی زندگی نہ پائے گا تو درخت ہمیشہ پھل کس طرح دے گا.گو یہ مفہوم آئندہ کے متعلق ہے اور اس کا اس دنیا میں ثبوت دینا ناممکن ہے.لیکن کم سے کم یہ بات تو ظاہر ہے کہ صرف الہامی کتب ہی دائمی نجات کا وعدہ دیتی ہیں.انسانی کتب دائمی نجات کا وعدہ نہیں دیتیں.اور نہیں دے سکتیں کیونکہ دائمی زندگی ابدی زندگی والی ہستی ہی دے سکتی ہے اور وہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے.پس وہی کلام دائمی زندگی کا دعویٰ پیش کرسکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا مدعی ہو.اور اس دعویٰ میں بھی قرآن کریم سب دوسری کتب سے بڑھا ہوا ہے.ہمیشہ کی زندگی کا مضمون جس وضاحت سے اور جس طرح با دلائل قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اس سے دسواں حصہ بھی دوسری کتب میں نہیں.اگر ہے تو کوئی شخص پیش کرکے دیکھ لے.بِاِذْنِ رَبِّهَاکے الفاظ سے قرآن کریم کےفوق الطبیعی نتائج کی طرف اشارہ پانچویں خصوصیت اس آیت میں کلمہ طیبہ کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ بِاِذْنِ رَبِّھَا پھل دے.اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے نتائج طبیعی نہ ہوں بلکہ طبیعی نتائج سے بالا ہوں.طبیعی نتائج صرف اس قدر ثابت کرسکتے ہیں کہ اس کتاب نے قوانین قدرت کا اچھا نقشہ پیش کیا ہے.لیکن یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ کتاب کسی ایسی ہستی کی طرف سے ہے جو طبعیات پر حاکم ہے.یہ امر اس کتاب سے ثابت ہو سکتا ہے جو علاوہ طبیعی نتائج کے فوق الطبیعی نتائج بھی پیدا کرے.مثلاً ایک
Page 162
کتاب میں حکم ہے کہ فلاں شے کھاؤ فلاں نہ کھاؤ.اس کا طبیعی نتیجہ تو یہ ہوگا کہ اگر کھانے والی شےمفید ہے تو کھانے والے کو طاقت حاصل ہوگی.اور اگر مضر ہے تو اس سے بچنے سے اس کی صحت اچھی رہے گی.انسانی کتاب کا اثر یہاں تک ختم ہو جائے گا.لیکن الٰہی کتاب اس سے اوپر تک ہمیں لے جائے گی کیونکہ اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہم ایک زائد فعل بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اس عمل کو کرتے ہیں اور اس طرح ہمارا طبیعی فعل مذہبی بھی ہو جاتا ہے.پس ضروری ہے کہ اگر کتاب آسمانی ہے تو اس کے طبیعی نتائج کے علاوہ فوق الطبیعی نتائج بھی نکلیں.اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی ایسی علامات ظاہر ہوں کہ جو طبیعی نتائج سے ممتاز اور علیحدہ ہوں.اس امر میں بھی قرآن کریم دوسری کتب سے بدرجہ غایت اعلیٰ اور اکمل ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس طرح فوق الطبیعی نشانات آپ کے لئے اور آپ کے اتباع کے لئے ظاہر ہوئے وہ دوسری مثال نہیں رکھتے.اور آپؐ کے بعد بھی قرآن کریم پر سچے طور پر عمل کرنےو الے لوگوں کے ساتھ نشانات الٰہیہ کا سلسلہ اس طرح وابستہ چلا آیا ہے کہ ہر عقل مند اس سے بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ کسی ایسی ہستی کا تعلق ہے جو طبیعی قوانین پر حاکم ہے.اور جس پر خوش ہوتی ہے اس کے لئے غیر معمولی سامانوں سے نصرت کے سامان پیدا کردیتی ہے.حضرت مسیح موعود ؑ قرآن مجید کے بِاِذْنِ رَبِّهَاوالے نتائج کی تازہ مثال اس وقت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ جن کی برکت سے اس آیت کے اس قدر وسیع مطالب کھلے ہیں اس بِاِذْنِ رَبِّهَا والے نتائج کی تازہ مثال ہیں اور آپ کے بعد آپ کی جماعت سے بھی اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہے اور اسی سلوک کے ماتحت باوجود شدید مخالفت کے وہ روز بروز ترقی کررہی ہے.فَسُبْحَانَ اللہِ وَالْحَمْدُلِلہِ وَاللہُ اَکْبَرُ.لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس آیت میں جو مطالب بیان کئے گئے ہیں وہ وہمی نہیں بلکہ تم خود تجربہ کرکے دیکھ لو اپنی ذات میں ان امور کا مشاہدہ کرلو گے جو اس میں بیان ہوئے ہیں.
Page 163
وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ا۟جْتُثَّتْ مِنْ اور بری بات کا حال برے درخت کی طرح ہے جس کو زمین پر سے اکھاڑ (کر پھینک )دیا گیا ہو (اور) جسے فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۰۰۲۷ (کہیں بھی) قرار( حاصل) نہ ہو.حلّ لُغَات.خَبِیْثَۃٌ: خَبِیْثٌ کا مؤنث ہے.اور اَلْخَبِیْثُ کے معنے ہیں اَلنَّجَسُ پلید.گندی چیز.اَلرَّدِیُٔ الْمُسْتَکْرَہُ.ایسی ردی چیز جس سے نفرت پیدا ہو.اور انسان اسے قبول نہ کرسکے.کُلُّ حَرَامٍ ہر حرام شے کو خبیث کہتے ہیں اور تاج العروس میں ہے کہ خَبِیْث ہر بری چیز کے لئے بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے.مثلاً کَلَامٌ خَبِیْثٌ.یعنی برا کلام وغیرہ.وَالحَرَامُ السُّحْتُ یُسَمّٰی خَبِیْثًا.ہر قسم کے حرام کو خبیث کہتے ہیں.اَلمَالُ الْحَرَامُ وَالدَّمُ وَمَا أَشْبَھُہَا مِـمَّا حَرَّمَہُ اللہُ حرام مال اور خون جو اِن کے مشابہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس کو بھی خبیث کہتے ہیں.وَیُقَالُ فِی الشَّیْءِ الْکَرِیْہ اِلطَّعْمِ وَالرَّائِـحَۃِ خَبِیْثٌ مِثْلَ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْکُرَّاثِ وَلِذَالِکَ قِیْلَ مَنْ اَکَلَ مِنْ ھَذِہِ الشَّجَرَۃِ الْخَبِیْثَۃِ فَلَا یَقْرِبَنَّ مَجْلِسَنَا نیز بدمزہ بدبودار چیز کو خبیث کہا جاتا ہے.جیسے لہسن، پیاز، گندنا وغیرہ.اسی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خبیث پودوں یعنی لہسن پیاز وغیرہ سے کچھ کھائے وہ ہماری مجلس کے قریب نہ آئے.(اقرب) پس کلمہ خبیثہ کے معنے ہوں گے (۱) گندہ اور برا کلام جسے انسان سن نہ سکے.(۲) ایسا کلام جسے سن کر نفرت پیدا ہو.(۳) ایسا کلام جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے.(۴) ایسا کلام جس سے اعلیٰ نتیجہ نہ نکلے.(۵) ایسا کلام جس میں اچھی اور بری تعلیم ملی ہوئی ہو وہ فرد کے لئے فائدہ بخش مگر قوم کے لئے مضر ہو.اِجْتَثَّہٗ کے معنے ہیں اِقْتَلَعَہٗ.اس کو جڑھ سے اکھیڑ دیا.اورمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ا۟جْتُثَّتْمیں اِجْتُثَّتْ کے یہی معنے مراد ہیں.یعنے اُسْتُؤْصِلَتْ جڑھ سے اکھاڑا گیا.(اقرب) پس كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ ا۟جْتُثَّتْ کے معنے ہوں گے کہ وہ برا کلام جو دیرپا نہیں اور اعتراض پراپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا اور جلدی اس کا اثر باطل ہو جاتا ہے.قَرَارٌ.قَرَّ کا مصدر ہے اور قَرَّفِی الْمَکَانِ قَرَارًا کے معنے ہیں ثَبَتَ وَسَکَنَ کسی جگہ پر ٹھہرا اور قَرَار کے
Page 164
معنے ہوئے کسی جگہ ٹھہرنا.نیز قَرَار کے معنے ہیں مَا قُـرَّ فِیْہِ.جس میں ٹھہرا جائے.اَلْمُسْتَقَرُّ جائے قرار (اقرب) پس مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ کے معنے ہوں گے اس کے لئے کوئی ثبوت اور سکون نہیں.اس کے لئے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں.مراد یہ ہے کہ بری تعلیم کسی ملک میں قائم نہیں رہ سکتی اور اس کے اصول بدلنے کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے.تفسیر.جھوٹے مذہب کی علامات شجرۃ طیّبۃ کے مقابلہ میں جو باتیں جھوٹے مذہب کے متعلق پیش کی گئی ہیں یہ ہیں: (۱) اس کی شکل مکروہ ہو.(۲) اعلیٰ اور فاسد تعلیموں کو ملا کر پیش کرتا ہو.(۳) اعلیٰ نتائج نہ نکلیں.یعنی اس پر چل کر کوئی آدمی ایسے پیدا نہ ہوں جو خدا تعالیٰ تک پہنچ سکیں.جیسے بہائی مذہب ہے کہ اسے ظاہر ہوئے قریباً نوے سال ہو گئے ہیں.(یعنی باب کے دعویٰ سے لے کر اس وقت تک ) لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جس نے کہا ہو کہ اس تعلیم پر چل کر مجھ سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آئے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ ان کے پیروؤں میں سے سینکڑوں گنائے جاسکتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں.اجتثت کے لفظ سے کلمہ خبیثہ کی صفات بتائی گئی ہیں.کلمہ خبیثہ کی صفات (۱) یہ کہ اس کلام میں سطحی مسائل پر بحث ہو روحانی امور پر نہ ہو.بلکہ ایسی باتیں ہوں جن کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں.(۲) اس کی تعلیم دیرپا نہ ہو.بہائی تعلیم کا یہی حال ہے کہ بہاء اللہ نے لکھا دوشادیاں تک جائز ہیں(اقدس صفحہ ۱۸).عباس نے اسے تبدیل کر دیا.(۳) اس کی تعلیم اعتراضات کا مقابلہ نہ کرسکے.ذرہ سے اعتراض سے اس کے پیروؤں کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے.بہائی تعلیم کا یہی حال ہے.وہ لوگ کبھی ایک مقام پر کھڑے نہیں رہ سکتے.ہر اعتراض پر اپنی جگہ بدل لیتے ہیں.(۴) جلدی اس کے اثر کو باطل کر دیا جائے.دیرپا تعلیم تو وہ ہے کہ لمبے زمانہ تک اس کا اثر رہے اور جلدی باطل ہونے والی وہ ہے کہ جلدی ہی قلوب اس سے پھرنے شروع ہو جائیں.اس کی مثال کے طور پر اسلامی زمانہ کے اول حصہ میں مسیلمہ وغیرہ کی تعلیم کو پیش کیا جاسکتا ہے.اور اس زمانہ میں بہائی مذہب کو پیش کیا جاسکتا ہے.خود اس کے اتباع اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے.آج تک کسی ایک گاؤں میں بھی کوئی ایسی جماعت نہیں پائی جاتی جو
Page 165
بہائی تعلیم پر عمل کرتی ہو.(۵) تازہ امداد اس کو نہ ملتی ہو.یعنی وحی الٰہی کا سلسلہ اس میں جاری نہ ہو.(۶) اس کے فروع بلند نہ ہوں.یعنی اعلیٰ درجے کے اخلاق پر حاوی نہ ہو.اور ہر قسم کی ضرورت ہائے انسانی پر اس میں بحث نہ ہو.مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ کےد و معنی ’’مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ‘‘ (۱) وہ کسی ملک میں قائم نہ رہ سکے.یعنی اس کو ایسا موقعہ ہی نہیں دیا جاتا کہ اس کا تجربہ کرکے دنیا کوئی نتیجہ نکالے.بغیر تجربہ ہی وہ مر جاتی ہے.(۲) اس کے اصول کو بدلنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے.اسلام نے شروع سے ’’ لَااِلٰہَ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہِ‘‘ کہا اور بعد میں کوئی تبدیلی اس میں نہ ہوئی.لیکن جو جھوٹا مذہب ہوگا اس میں اصول کو ہمیشہ بدلنا پڑے گا.مثال کے طور پر بہائیوں کو دیکھ لو.ایران میں جاؤ تو وہاں بہائیت کی تعلیم اور رنگ میں پیش کی جاتی ہے.کیونکہ وہاں شیعہ ہیں.سنی ممالک میں اسی مذہب کی تعلیم اور رنگ میں پیش کی جاتی ہے.امریکہ میں جاکر اصول بالکل مختلف کر دیئے گئے ہیں.اسی طرح انگلستان میں وہ باتیں پیش کی جاتی ہیں جن کو وہاں کے لوگ قبول کرنے کے لئے تیا رہوں.مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍکی ایک مثال چنانچہ جب میں انگلستان گیا تو بہائیوں میں سے ایک عورت نے میرے ساتھ گفتگو کی.میں نے کہا بہاء اللہ نے کون سی نئی بات پیش کی ہے.اس نے کہا کہ بہاء اللہ نے کہا ہے کہ ایک ہی عورت سے شادی کرنی چاہیے.میں نے کہا کہ اس نے خود دو بیویاں کی ہوئی تھیں.پہلے اس نے انکار کیا پھر کہا کہ وہ دعویٰ سے پہلے کی بات ہے.میں نے کہا جب وہ نعوذباللہ خدا تھا تو پھر پہلے اور پیچھے کا تو سوال ہی نہیں.عالم الغیب ہستی کے لئے پہلے پیچھے کوئی معنے نہیں رکھتا.اس کو پہلے ہی علم ہونا چاہیے تھا کہ میں آگے چل کر کیا تعلیم دینے والا ہوں.نیز اس نے دعویٰ کے بعد اپنے بیٹے عباس کو دو بیویاں کرنے کی اجازت دی.کیونکہ اس کے ہاں اولاد نہ تھی.اس پر اس عورت کے کان میں ایک ایرانی بہائی عورت نے جو ایران کی تھی چپکے سے کہا کہ دوسری بیوی کو بہاء اللہ نے بہن بنا لیا تھا.اور یہی بات اس انگریز عورت نے دوہرا دی.اس پر میں نے کہا کہ بہاء اللہ کے دعویٰ کے بعد دونوں عورتوں سے اولاد ہوئی ہے.کیا بہن کے ہاں اولاد پیدا کی گئی تھی.اس پر وہ حیران ہو کر اپنی دوست سے پوچھنے لگی کہ کیا دعویٰ کے بعد دوسری عورت کے ہاں اولاد ہوتی رہی ہے؟ اور جب اس نے کہا کہ ہاں تو مجلس میں سب ہنس پڑے کہ ابھی تو بہن قرار دیا تھا اور ابھی اس کے ہاں اسی زمانہ میں اولاد کا ہونا بھی تسلیم کر لیا.غرض بہائی لوگ ہر ملک
Page 166
میں جاکر علیحدہ قانون بناتے ہیں.یہی حال عیسائیت کا ہے.چنانچہ ان کی مشنری کتب میں کھلے طور پر بحثیں ہوتی رہتی ہیں کہ ہر قوم کے آگے کس رنگ میں مسیح علیہ السلام کو پیش کرنا چاہیے.شروع مسیحیت میں بھی روم والوں نے جب مطالبہ کیا کہ سبت ہفتہ کی جگہ اتوار کو ہو تو مسیحیوں نے ان کی خاطر ہفتہ کی بجائے سبت اتوار کو قرار دے دیا.اس کے بالمقابل اسلام کو دیکھو شروع سے لے کر اس وقت تک سب تعلیم ایک جڑھ پر قائم ہے.نہ کم کرنے کی ضرورت ہوئی نہ زیادہ کرنے کی.يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اللہ( تعالیٰ) اس قائم رہنے والی (اور پاک) بات کے ذریعہ سے (اس) ورلی زندگی الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ١ۚ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ١ۙ۫ وَ يَفْعَلُ میں (بھی) ثبات بخشتا ہے اور آخرت (کی زندگی) میں بھی( بخشے گا) اور ظالموں کو اللہ(تعالیٰ) ہلاک کرتا ہے اللّٰهُ مَا يَشَآءُؒ۰۰۲۸ اور اللہ( تعالیٰ) جو چاہتا ہے کر تا ہے.حلّ لُغَات.یُثَبِّتُ: ثَبَّتَ کا مضارع ہے.جس کا مجرد ثَبَتَ ہے اور ثَبَتَ الْاَمْرُ عِنْدَ فُلَانٍ کے معنے ہیں تَحَقَّقَ وَ تَأَکَّدَ.کوئی امر کسی کے نزدیک یقینی طور پر ثابت ہو گیا.ثَبَتَ فُلَانٌ عَلَی الْاَمْرِ.دَاوَمَہٗ.کسی کام پر دوام اختیار کیا.وَاَثْبَتَہٗ وَثَبَّتَہٗ.جَعَلَہٗ ثَابِتًا فِی مَکَانِہٖ لَایُفَارِقُہٗ.اور اَثْبَتَہٗ اور ثَبَّتَہٗ کے معنے ہیں اس کو اس کی جگہ پر ایسے طور پر ثبات بخشا اور مضبوط رکھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے.سو ثَابِتٌ کے معنے ہوں گے اپنی جگہ پر مضبوط رہنے والا.(اقرب) پس يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ کے معنے ہوں گے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قائم رہنے والی اور مضبوط بات کے ذریعہ سے ثبات اور اپنی جگہ پر مضبوط رہنے کی طاقت بخشتا ہے.یُضِلُّ یُضِلُّ اَضَلَّ سے مضارع ہے اور اَضَلَّ کے معنے ہیں اَھْلَکَہٗ اسے ہلاک کیا.(اقرب) تفسیر.وہ قول جو ثابت ہے وہ وہی ہے جو کلمہ طیبہ کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے.یعنی اس کی تائید کے لئے
Page 167
اللہ تعالیٰ الہام نازل کرتا ہے.اس کو ثابت اس لئے کہا کہ آج ان کو اور کل ان کے بھائیوں کو حاصل ہو گا.ا ور کبھی یہ سلسلہ نہ ٹوٹے گا.اور پھر اس وجہ سے بھی ثابت کہا کہ اس کا اثر یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی ہوگا.لیکن اس کے خلاف جھوٹے مدعیوں کا کلام مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دیتا.وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ١ۙ۫ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ظالم وہ ہیں جو کلام الٰہی میں عِوَج چاہتے اور اس کے راستہ میں روکیں ڈالتے ہیں.اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرے گا سے یہ مراد ہے کہ قرآن کریم کی اشاعت اور اس کے دنیا میں قائم ہوجانے کے متعلق اور اس کے مخالفوں کی تباہی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ پورا کر کے دکھا دے گا.اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحَلُّوْا (اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں( کی حالت) کو( غور کی نظر سے) نہیں دیکھا جنہوں نے ناشکری سے قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِۙ۰۰۲۹ اللہ( تعالیٰ) کی نعمت کو بدل ڈالا(اور آپ بھی ہلاک ہوئے )اوراپنی قوم کو( بھی) ہلاکت کے گھر میں (لا) اتارا.حلّ لُغَات.بَـوَارٌ بَارَ یَبُوْرُ کا مصدر ہے اور بَارَ کے معنے ہیں ھَلَکَ.ہلاک ہو گیا.بَارَ السُّوْقُ وَالسِّلْعَۃُ کَسَدَتْ.سامان یا بازار کا بھاؤ گِر گیا.بَارَ الْعَمَلُ بَطَلَ کام باطل ہو گیا.بَارَالْاَرْضُ بَوْرًا لَمْ تُزْرَع زمین میں کسی قسم کی کھیتی نہ بوئی گئی.بَارَ زَیْدٌ عَمْرًا جَرَّبَہٗ وَاَخْتَبَرَہٗ.زید نے عمر کا امتحان لیا.وَ مِنْہُ کُنَّا نَبُوْرُ اَوْلَادَ نَا بِـحُبِّ عَلِیٍّ.اور انہی معنوں میں یہ قول ہے جس کے معنے ہیں ہم اولاد کا امتحان لیا کرتے تھے کہ وہ حضرت علی سے کتنی محبت رکھتے تھے.اَلْبَوَارُ اَلْھَلَاکُ.ہلاکت.اَلْکَسَادُ.کسی چیز کی مانگ نہ ہونا (اقرب) پس دَارُالْبَوَارِ کے معنی ہوئے ہلاکت کا گھر.دَارُالْاِمْتِحَانِ امتحان کا گھر.دَارُالْکَسَادِ ایسا گھر جس کی طرف رغبت نہ ہو.تفسیر.خدا کی نعمت کو کفر سے بدلنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے تو ان پر انعام کیا تھا انہوں نے یہ بدلہ دیا کہ احسان فراموشی سے کام لے کرا س احسان کا یعنی کلمہ طیبہ کا انکار کرکے قوم کو ہلاک کر دیا.
Page 168
جَهَنَّمَ١ۚ يَصْلَوْنَهَا١ؕ وَ بِئْسَ الْقَرَارُ۰۰۳۰ یعنی جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ جگہ( رہنے کے لحاظ سے) بہت بری ہے حل لغات اَلْقَرَارُ کے لئے دیکھو حل لغات آیت نمبر ۲۷.تفسیر.یعنی کلمہ طیبہ کا انکار لازماً تباہی میں ڈالتا ہے اور وہ تباہی بھی جلا دینے والی تباہی ہوتی ہے.وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ١ؕ قُلْ تَمَتَّعُوْا اور انہوں نے اللہ( تعالیٰ) کے ہم رتبہ (اور مخالف) شریک بنا لئے ہیں.تا( لوگوں) کو اس کی راہ سے برگشتہ فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ۰۰۳۱ کریں.تو( انہیں) کہہ (کہ اچھا یہ )عارضی فائدہ اٹھالو.(پھر اس وقت کو یاد کروگے) کیونکہ( ایک دن) تمہیں یقیناً( دوزخ کی) آگ کی طرف جانا ہوگا.حل لغات.اَنْدَادٌ.نِدٌّ کی جمع ہے اور نِدٌّ کے معنے ہیں اَلْمِثْلُ.مثل.ہم رُتبہ.وَلَایَکُوْنُ اِلَّا مُخَالِفًا.لفظ نِدٌّ کا استعمال صرف اس نظیر کے لئے ہوتا ہے جو مخالف ہو اور مَالَہٗ نِدٌّ کے معنے ہوں گے مَالَہٗ نَظِیْرٌ کہ اس کا کوئی مثل ہم رتبہ نہیں.(اقرب) تفسیر.انہوں نے خدا تعالیٰ کے مخالف شریک بنائے ہیں سے یہ مراد نہیں کہ وہ واقعہ میں خدا کے مخالف ہیں یا یہ کہ مشرک انہیں خدا تعالیٰ کے مخالف قرار دیتے ہیں.بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بتوں کا وجود ہی خدا تعالیٰ کی شان کے مخالف ہے.اگر ان کو مانا جائے تو پھر خدا خدا نہیں رہتا.مطلب یہ کہ کلمہ طیبہ کو چھوڑ کر کن لغو باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
Page 169
قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُنْفِقُوْا مِمَّا (اے رسول )میرے ان بندوں سے جو ایمان لا چکے ہیں (ان سے) کہہ کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا نہ کوئی بیع (و شراء) ہوگی اور نہ( ہی) کوئی گہری دوستی نماز کو عمدگی سے ادا کیا کریں.اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خِلٰلٌ۰۰۳۲ اس میںسے پوشیدگی میں (بھی) اور ظاہر میں (بھی ہماری راہ میں) خرچ کیا کریں حلّ لُغَات.خِلَالٌ خُلَّۃٌ کی جمع ہے اور خُلَّۃٌ خَالَّ سے ہے.خَالَّہٗ مُخَالَّۃً وَخِلَالًا وَخَلَالًا کے معنے ہیں صَادَقَہٗ وَآخَاہُ.اس سے دوستی کی اور اس کا بھائی بنا.اَلْـخُلَّۃُ اَلْمَحَبَّۃُ وَالصَّدَاقَۃُ لَاخَلَلَ فِیْھَا.ایسی محبت اور دوستی جس میں کوئی خلل نہ ہو.(اقرب) تفسیر.اگر مومن شجرہ طیبہ یا الہامی کلام کے فوائد کو جلد لانا چاہتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ وہ نمازوں کو ہمیشہ اور باشرائط ادا کیا کریں اور اپنے مالوں کو چھپ چھپ کر اور ظاہراً بھی خرچ کیا کریں.ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا نمازی نہیں کہلا سکتا اس حکم سے میرے نزدیک یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جو شخص ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ نمازی نہیں کہلا سکتا.اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ اللہ (تعالیٰ) وہ( ہستی) ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور بادلوں سے پانی اتارکر اس کے ذریعہ سے مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ١ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ تمہارےلئے پھلوں (کی قسم) سے رزق پیدا کیا ہے.اور اس نے کشتیوں کو بلا اجرت تمہاری خدمت پر لگایا (ہوا)
Page 170
الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ١ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَۚ۰۰۳۳ ہے تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں اور دریاؤں (اور نہروں) کو (بھی) اس نے بلا اجرت تمہاری خدمت پر وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآىِٕبَيْنِ١ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ لگا رکھا ہے.اور اس نے سورج اور چاند کو (بھی) بلا اجرت تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے درآنحالیکہ وہ بلا وقفہ وَ النَّهَارَ۰۰۳۴ (اپنا مفوضہ) کام کرتے ہیں اور اس نے رات اور دن کو (بھی) بلا اجرت تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے.حلّ لُغَات.دَائِبَیْنِ دَأَبَ یَدْأَبُ دَأَ بًا فِی عَمَلِہٖ.جَدَّ وَ تَعِبَ وَاسْتَمَرَّ.کام میں محنت کی اور لگاتار کام کیا.(اقرب) دَائِبٌ کے معنے ہیں محنت سے اور لگاتار کام کرنے والا اور دَائِبَیْنِ اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے.پس دَائِبَیْنِ کے معنے ہوں گے کہ وہ دونوں بلاوقفہ اور متواتر کام کرنے والے ہیں.تفسیر.دونوں آیات میں نعمتوں کا ذکر کرکے مومنوں کو ایک نصیحت ان دو آیات میں نعمتوں کا ذکر کرکے اور اپنے احسانات یاد کراکے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی ہیں.اگر تم بجائے ان سے کام لینے کے بیوقوفی سے انہیں پوجنے لگو گے تو نعمت کی ناقدری کی وجہ سے وہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی.دوسرے یہ بتایا ہے کہ جب یہ نعمتیں ہماری ہیں تو جو ہمارے کلمہ سے تعلق رکھتے ہیں ہم انہی کو ان سے متمتع کریں گے.چنانچہ دیکھ لو کس طرح یہ سب چیزیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں لگ گئیں.دن بھی ان کے ہو گئے اور راتیں بھی.سمندر بھی ان کے اور جہاز بھی ان کے.ان دونوں آیتوں سے پہلےلِیُقِیْمُوْا الصَّلٰوةَ وَ يُنْفِقُوْا فرمایا تھا.ان امور کا تعلق ان دونوں آیتوں سے یہ ہے کہ اقامت صلوٰۃ شرک سے مخالف ہے.گویا پہلے سے ہوشیار کر دیا کہ نعمتیں ملنے والی ہیں.ایسا نہ ہو کہ شرک کرنے لگو.پھر وَ يُنْفِقُوْا کا حکم دے کر اس امر سے ہوشیار کیا کہ جس طرح بعض نعمتوں کو انسان خدا بنا لیتا ہے اور بعض کو ذاتی ملکیت سمجھ لیتا ہے تم یاد رکھنا کہ خدا تعالیٰ نے ان سب کو تم سب کے لئے مسخر کیا ہے اس لئے نہ تو ان کو خدا بنانا اور نہ دوسرے بندوں کو محروم کرکے ان پر اپنا واحد قبضہ جمانا.بلکہ خدا تعالیٰ کی سب مخلوق کو ان میں شریک کرنا اور سب کو حصہ دینا.کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ نعمتیں سب انسانوں کے لئے پیداکی ہیں.نہ کہ کسی خاص گروہ کے لئے.سب بندوں کا اس میں حصہ ہے.پس تم ان کو
Page 171
دوسروں میں بانٹتے رہنا.وَ اٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ١ؕ وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اور جو کچھ( بھی) تم نے اس نے مانگا اس نے تمہیں دیا ہے اور اگر تم اللہ( تعالیٰ) کے احسان گننے لگو تو ا ن کا شمار نہیں لَا تُحْصُوْهَا١ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌؒ۰۰۳۵ کر سکو گے.انسان یقیناً بڑا ظالم (اور) بڑا شکر ناگذار ہے.تفسیر.مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ کا مطلب.جس بات کا انسانی فطرت تقاضا کرتی تھی وہ سب خدا تعالیٰ نے مہیا کر دیا مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ اگر اس کو ماضی کے معنوں میں مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس بات کا انسانی فطرت تقاضا کرتی تھی وہ سب کا سب خدا تعالیٰ نے مہیا کر دیا.زبانی سوال مراد نہیں.کیونکہ زبانی سوال تو کئی رد بھی کر دیئے جاتے ہیں مگر تقاضائے فطرت کبھی رد نہیں کیا جاتا.انسان میں اگر تاثر کی طاقت رکھی ہے تو ساتھ ہی تاثیر کرنے والی چیزیں بھی پیدا کر دیں اور اگر اس میں تاثیر کا مادہ رکھا ہے تو اس کے اثر کو قبول کرنے والی چیزیں بھی بنا دی ہیں.آنکھ دیکھنے کے لئے بنائی ہے تو اس کے لئے روشنی کے سامان اور خوبصورت نظارے بھی پیدا کئے.کان سننے کے لئے بنائے تو اس کے لئے ہوا اور خوش الحان اور سریلی آوازیں بھی پیدا کیں.مرد میں تولید کا مادہ پیدا کیا تو اس کے قبول کرنے کے لئے عورت بھی پیدا کر دی.غرض ہر تقاضائے فطرت کا جواب پیدا کیا ہے اور یہی اس آیت کے معنے ہیں.مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ میں ماضی بمعنی مضارع (۲) ماضی بمعنی مضارع بھی ہوسکتی ہے.جب یہ یقین دلانا ہو کہ جس امر کا وعدہ ہے اسے تم پورا ہوا ہی سمجھو تو مضارع کی جگہ ماضی کا صیغہ بھی لے آتے ہیں.اس صورت میں آیت کے معنے یہ ہوں گے کہ اے مومنو! تم نے جو خدا سے خواہش کی ہے کہ وہ ایسے علاقے تم کو دے جن میں قرآن کریم کی تعلیم استوار ہو اور جڑھ پکڑے وہ قبول ہو گئی اور سن لو کہ آسمان و زمین کی کل چیزیں تمہارے سپرد کی جائیں گی اور دنیا میں تمہارے لئے سہولتیں اور آسائشیں بہم پہنچائی جائیں گی.مومن بحیثیت جماعت خدا تعالیٰ سے یہی مانگا کرتا ہے کہ دین کی اشاعت ہو اور دین کی ترقی کے راستے میں کوئی روک نہ رہے اور یہ سورۃ بھی مکی ہے.اس زمانہ میں مسلمانوں کے راستہ میں سخت مشکلات تھیں.مومن
Page 172
دعائیں کرتے تھے کہ کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں ہم آزادی سے اسلام کی تعلیم کو رائج کر سکیں.تو ان کے جواب میں فرمایا کہ بے شک ایسے علاقے مسخر کر دئیے جائیں گے.جن میں تم آسانی کے ساتھ اسلامی تعلیم کو قائم کرسکو گے.اب پھر اسلام پر ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ اس کی تعلیم پر کلی طور پر عمل نہیں کیا جاسکتا.اور بعض علاقوں میں تو اس کے لئے سب راہیں مسدود ہیں.جیسے روس کا علاقہ ہے.تبلیغی لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں سچائی کی تبلیغ اس وقت کہیں بھی نہیں ہو سکتی.علماء امراء، آقاؤں، بادشاہوں اور غلاموں وغیرہ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق دین کو بدل دیا ہے.ان حواشی کو علیحدہ کرکے سچے اسلام کی تبلیغ کسی ملک میں بھی نہیں ہوسکتی.پس ہر مخلص مومن کو چاہیے کہ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ پر عمل کرے اور خدا سے دعا کرے تا وہ تبلیغ اسلام کے لئے آسانیاں میسر فرمائے اور اسلام کے قیام کے سامان پیدا کرے.اور یہ دعائیں انہی لوگوں کی قبول ہوں گی جو اقامۃ صلوٰۃ کرنے والے ہوں گے.جو لوگ نمازیں باقاعدہ اور بلا سخت معذوری کے باجماعت ادا نہیں کرتے ان کی دعا کم سنی جاتی ہے.اسی طرح یہ دعا انہی کی سنی جائے گی جو اخلاص سے اسلام کے لئے مالی قربانیاں کرنے والے ہوں گے.جماعت احمدیہ کو ایک نصیحت جماعت احمدیہ بے شک چندے دیتی ہے لیکن صحابہ والا انفاق اور تھا.وہ تو کوشش کرکے اپنے اوپر غربت لاتے تھے.جب تک اسی طرح انفاق نہ ہو ترقی ممکن نہیں ہوا کرتی.اسی وجہ سے پہلی آیت میں جہاں خرچ کا حکم دیا ہے وہاں سرًّا کو پہلے رکھا ہے.یہ بتانے کے لئے کہ اصل انفاق وہ ہے جو طبعی ہو اور اس میں کسی شہرت وغیرہ کا خیال نہ ہو.جو انفاق طبعی ہو گا ظاہر ہے کہ اس کے لئے طبیعت کو ابھارنا نہیںپڑے گا.بلکہ اسکے ظہور کو بعض دفعہ روکنے کی ضرورت محسوس ہوگی.پس وہی انفاق اس آیت کے ماتحت ہے جو طبعی ہو نہ یہ کہ نفس پر خرچ کرنا تو طبعی ہو اور خدا کے راستہ میں خرچ کرنے کے لئے دوسرے کے کہنے کی ضرورت ہو.جب احمدیہ جماعت میں یہ مادہ پیدا ہو جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر خرچ کرنے کے لئے تو نفس پر بوجھ ڈالنا پڑے گا اور دین کی راہ میں خرچ کرنا طبعی تقاضا مدنظر آئے گا تب ان کے لئے ترقیات کے راستے کھلیں گے.اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰہِسے مراد آئندہ کے افضال ہیں اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْھَا.یہ مراد نہیں کہ ان احسانات کی ظاہری گنتی نہیں کرسکتے.یہ تو ایک موٹی بات ہے.انسان اگر اپنے جسم کی نعمتوں کو ہی شمار کرنا چاہے تو وہ بھی بے حد وبے قیاس ہیں.پس اس سے مراد آئندہ کے افضال ہیں.یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تم پر ہوں گی.مختلف قسم کے احسان تم سے وہ کرے گا اور اتنے فضل تم پر نازل ہوں گے کہ تم احاطہ بھی نہ کرسکو گے.لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌسے مراد لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ کہہ کر یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر ان نعمتوں کے باوجود لوگ اسلام سے
Page 173
غفلت برتیں گے تو وہ ظلوم بھی ہوں گے اور کفار بھی.ظلوم اس طرح کہ ایک نئی اور پاک دنیا جو اسلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قائم کرے گا وہ اس کے تباہ کرنےو الے ہوں گے.اور کفار اس لئے کہ ان گنت احسانات کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے ناشکری کا معاملہ کرنے والے ہوں گے.وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اور (اے مخاطب اس وقت کو یاد کر) جب ابراہیم نے (دعا کرتے ہوئے)کہا تھا (کہ) اے میرے رب اس اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَؕ۰۰۳۶ جگہ کو امن والی (جگہ )بنا.اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے دور رکھ کہ ہم معبودان باطلہ کی پرستش کریں حلّ لُغَات.وَاجْنُبْنِیْ جَنَبَہٗ جَنْبًا دَفَعَہٗ.اس کو دور کیا.جَنَبَ زَیْدًا اَلشَّیْءَ نَـحَّاہُ عَنْہُ.اس نے زید کو کسی چیز سے ایک طرف رکھا.وَمِنْہُ فِی الْقُرْاٰنِ وَاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنَامِ.اَیْ نَحِّنیْ وَاِیَّاھُمْ کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے ایک طرف رکھیو (اقرب) یعنی اے خدا !جب تو نے ہمیں طہارت بخشی ہے تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ اس پر قائم رکھیو.اَلْاَصْنَامُ.اَصْنَامٌ صَنَمٌ کی جمع ہے.اس کے معنے ہیں اَلْوَثَنُ.بت.وَھُوَ صُوْرَۃٌ أَو تِمْثَالُ اِنْسَانٍ اَوْحَیَوَان یُتَّخَذُ لِلْعِبَادَۃِ.یہ انسان یا حیوان کے اس مجسمہ پر بولا جاتا ہے جو عبادت کی خاطر بنایا جاتا ہے.کُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللہِ.ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے.یہ معرب ہے.(یعنی لغت والے کے نزدیک یہ لفظ عربی زبان کا نہیں.دوسری زبان سے مانگا ہوا ہے) لیکن عربی زبان میں صَنَمٌ کا لفظ استعمال ہوتا ہے.جیسے کہتے ہیں صَنِمَتِ الرَّائِـحَۃُ.خَبُثَتْ.ہوا بدبودار ہو گئی.الْعَبْدُ قَوِیَ.طاقتور ہو گیا.صَنَّمَ الرَّجُلُ صَوَّتَ آدمی نے آواز نکالی.اَلصَّنَمَۃُ قَصَبَۃُ الرِّیْشِ کُلُّھَا.پورا سرکنڈا.الدَّاھِیَۃُ.مصیبت (اقرب) تفسیر.یہ بتاچکنے کے بعد کہ پہلے انبیاء بھی بے سامان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ غیرمرئی اسباب سے کامیاب ہوئے.آنحضرت ؐ کی کامیابی کی بنیاد ہزاروں سال پہلے سے رکھی گئی اسی طرح اب محمد رسول اللہ صلعم غیرمرئی اسباب سے جن میں سے ایک مثال کلمہ طیبہ کی تمثیل سے مستنبط دلائل ہیں کامیاب ہوں گے.اس آیت میں یہ بتایا
Page 174
گیا ہے کہ اس رسول کی کامیابی کی بنیاد تو ہزاروں سال پہلے سے رکھی گئی ہے.خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے.چنانچہ فرماتا ہے کہ مکہ والوں کو الہامی کتاب کی نعمت سے متمتع کرنا ضروری تھا اور انہیں شرک کی ظلمت میں پڑا رہنے نہیں دیا جاسکتا تھا.کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بارہ میں حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے وعدہ کر چکا ہے اور وہ وعدہ خلاف نہیں ہے.حضرت ابراہیم کو دعا کرتے وقت علم تھا کہ مکہ میں شرک پھیلے گا اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اس امر کا علم رکھتے تھے کہ مکہ کے علاقہ میں شرک پھیلنے والا ہے.تبھی تو انہوں نے دعا کی کہ خدایا مجھے اور میری اولاد کو شرک سے ایک طرف رکھیو.ورنہ جس وقت دعا کی گئی تھی مکہ میں شرک کا نام و نشان نہ تھا.صرف حضرت اسمٰعیلؑ کا گھر آباد تھا یا وہ لوگ بستے تھے جو ان کے تابع تھے.موازنہ مذاہب والوں کے خیال کا رد اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توحید اور شرک کے دور دنیا پر آتے رہتے ہیں اور موحد قومیں مشرک ہو جاتی ہیں اور مشرک موحد ہوجاتی ہیں اور توحید کے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی قوم کی نسبت بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اب وہ شرک کے اثر سے محفوظ ہو گئی ہے.اس تعلیم سے اس خیال کا رد ہوتا ہے جو موازنہ مذاہب والے لوگ پیش کرتے ہیں.یعنی توحید شرک سے ترقی کرتے کرتے پیدا ہوتی ہے.قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بعد شرک اور شرک کے بعد توحید کے دور آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ توحید کا دور شرک کے دور سے پہلے ہوتا ہے.اس اصل کے ماتحت توحید کو الہامی اور شرک کو تنزل کا ایک مقام تسلیم کرنا پڑتا ہے.برخلاف موزانہ مذاہب والوں کے اصول کے کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا خیال خوف اور حیرت سے پیدا ہوا اور شرک سے ترقی کرتے ہوئے توحید کے نقطہ تک پہنچا.بظاہر یہ اختلاف معمولی معلوم ہوتا ہے مگر اسی اختلاف کے نتیجہ میں مذہب نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور موازنہ مذاہب والوں نے کہا کہ انسان نے خدا کو پیدا کیا ہے.یعنی خدا تعالیٰ کا خیال انسانی دماغ کی ایجاد ہے اور اس کی تکمیل انسانی فلسفہ کی تکمیل سے ہوئی ہے.اس آیت پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم شرک کرسکتے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے یہ دعا کیوں کی کہ خدایا مجھے شرک سے بچا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی طاقتیں دو قسم کی ہیں.ایک وہ جو خِلْقَۃً اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں.ان کے متعلق وہ دعا نہیں کرتا.مثلاً یہ نہیں کہتا کہ خدایا میرا ایک ہی سر رہے دو نہ ہو جائیں.دوسری وہ طاقتیں ہیں جو انسان کو کَسْبًا یا وَہْبًا ملتی ہیں.یعنی وہ انہیں آپ ترقی کر کے حاصل کرتا ہے.یا خدا تعالیٰ کا خاص فضل دوسرے انسانوں سے ممتاز کرکے اسے عطا کرتا ہے.ایسی طاقتوں میں چونکہ تنزل کا امکان ہوتا ہے ان کے لئے دعا جاری
Page 175
رکھی جاتی ہے.خواہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی کیوں نہ ہو کہ وہ اس انعام سے اسے متمتع رکھے گا.کیونکہ اس دعا میں درحقیقت اس امر کا اقرار ہوتا ہے کہ یہ نعمت میری ذاتی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے بطور انعام حاصل ہوئی ہے.اسی اصل کے ماتحت انبیاء نبوت کے انعامات کے متعلق بھی دعا میں لگے رہتے ہیں.جیسے حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا یا استغفار اور توبہ کا انبیاء سے صدور ہے.انبیاء کا استغفار ان نکتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے انبیاء کے استغفار اور توبہ سے دھوکا کھایا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے کہ گویا وہ گنہگار تھے.حالانکہ ان کے استغفار اور توبہ کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ جس مقام طہارت پر وہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موہبت ہے اور اس کے جاری رکھنے کے لئے وہ دعا کرتے ہیں کیونکہ اس کا تسلسل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتا ہے.باوجود کمال کے انسان کو اللہ تعالیٰ پر سہارا رکھنا چاہیے اسی بناء پر قرآن کریم میں بار بار وَعَلَی اللّٰہِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکَّلُوْنَ آتا ہے.یعنی باوجود کمال کے انسان کو اللہ تعالیٰ پر سہارا رکھنا چاہیے.کیونکہ وہ کمال خدا تعالیٰ پر سہارے سے ہی حاصل ہوا ہے.اور اس سہارے کا اقرار کرتے رہنا اپنے لئے اور دوسروں کے لئے ہدایت کا موجب ہوتا ہے.رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ١ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ اے میرے رب انہوںنے یقیناً بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے پس جس نے میری پیروی (اختیار ) کی وہ (تو) فَاِنَّهٗ مِنِّيْ١ۚ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰۰۳۷ مجھ سے (تعلق رکھتا ہے) اور جس نے میری نافرمانی کی تو (اس کے متعلق بھی میری یہی عرض ہے کہ ) تویقیناً بڑا ہی بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے تفسیر.حضرت ابراہیم ؑ کی محبت الٰہی کا مظاہرہ محبت الٰہی کا کیسا پاک مظاہرہ ہے.حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں میری اولاد اگر شرک نہ کرے گی تب تو وہ میری اولاد ہے ورنہ نہیں.اس آیت سے یہ بھی مستنبط ہے کہ بہت سے گناہوں کا باعث اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے.اولاد کی محبت اس حد تک ہونی چاہیے جس سے وہ بگڑ نہ جائے حضرت ابراہیمؑ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ
Page 176
اولاد کی محبت اس حد تک ہونی چاہیے جس سے وہ بگڑ نہ جائے.ایسی محبت جو اولاد کو خراب کر دے محبت نہیں دشمنی ہے.جسمانی آرام سے روحانی اور اخلاقی درستی کا خیال مقدم رہنا چاہیے.اگر اولاد باوجود کوشش کے درست نہ ہو تو ایک وقت ایسا آسکتا ہے کہ اس سے قطع تعلق کرنا ضروری ہو.کیونکہ جب ان کو معلوم ہو کہ ماں باپ ہماری غلطی سے چشم پوشی کرتے ہیں تو وہ غلط راہ پر چلتے جاتے ہیں.لیکن جب ان کو معلوم ہو کہ ہماری غلطی پر مناسب گرفت ہوتی ہے تو ان کی اصلاح ہوتی جاتی ہے.اس لئے ہمیں چاہیے کہ اولاد کی محبت پر خدا کی محبت غالب رکھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی ہی خوشنودی کا موجب نہیں بلکہ اپنی اولاد کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے.وَ مَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ پہلے عرض کیا تھا کہ میری اولاد میں سے اگر کوئی شرک میں پڑ جائے تو وہ میری اولاد سے نہیں.مگر نبی میں رحم بھی ہوتا ہے اولاد کو اولاد نہ سمجھنا اور خدا کی محبت کو ترجیح دینا اور چیز ہے اور ان کے لئے خدا سے رحم کی درخواست کرنا اور چیز ہے.پس حضرت ابراہیم ؑ دعا کرتے ہیں کہ اول تو میری اولاد کو شرک سے بچائیے لیکن اگر ان میں سے کوئی میرے طریق کے خلاف کرے تو میں تو اسے یہی کہوں گا کہ وہ میری اولاد نہیں مگر تو چونکہ غفور رحیم ہے اس لئے تیرے غفور رحیم ہونے سے میں یہی امید کرتا ہوں کہ تو ان کے گناہ بخشیو اور ان کی ترقی کے سامان پیدا کرتا رہیو.اس میں یہ بتایا کہ اولاد سے ناراضگی کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے دل بھی سخت کرلے بلکہ سزا ظاہری ہو دل میں ان کے لئے دعا کرتا رہے اور ان کی اصلاح مدنظر رکھے نہ کہ ان کی تباہی چاہے.رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے معزز گھر کے پاس ایک وادی جس میں کوئی کھیتی (بھی) بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ١ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً نہیں (ہوتی لا) بسایا ہے.اے میرے رب (میں نے ایسا اس لئے کیا ہے) تا وہ عمدگی سے نماز ادا کیاکریں پس تو مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ (نیک) لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور انہیں (تازہ)پھلوں (کی قسم )سے (بھی) رزق دیتا رہ.
Page 177
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ۰۰۳۸ تاکہ وہ (ہمیشہ تیرا) شکر کرتے رہیں.حلّ لُغَات.اَلْوَادِیْ کے لئے دیکھیں سورۂ رعد آیت نمبر۱۸.اَفْئِدَۃٌ.فُؤَادٌ کی جمع ہے اور اَلْفُؤَادُ کے معنے ہیں اَلْقَلْبُ لِتَوَقُّدِہٖ.دل اور قلب کو فُواد اس کے احساسات کی تیزی کی وجہ سے کہتے ہیں.وَقِیْلَ لِتَحَرُّکِہِ.اور بعض نے قلب کو فُواد کہنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ حرکت کرتا ہے.کیونکہ فَأَدَ کے اصل معنی حرکت کرنے کے ہیں.وَقِیْلَ ھُوَ بَاطِنُ الْقَلْبِ اور بعض کے نزدیک فؤاد دل کے اندرونی حصہ کا نام ہے.وَقِیْلَ غِشَاؤُ ہٗ اور بعض کے نزدیک دل کے اوپر کے حصے کا وَقَالَ جَمَاعَۃٌ مِنَ الْمُفَسِّرِیْنَ یُطْلَقُ الْفُؤَادُ عَلَی الْعَقْلِ اور مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک فُواد کے معنے عقل کے ہیں.(اقرب) تَھْوِیْ.ھَوٰی سے مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ھَوَتِ الْعِقَابُ کے معنی ہیں اِنْقَضَّتْ عَلَی صَیْدٍ اَوْغَیْرِہٖ.باز اپنے شکار پر ٹوٹ پڑا.ھَوَتْ یَدِیْ لَہُ : اِمْتَدَّتْ وَارْتَفَعَتْ.ھَوَتْ یَدِیْ لَہُ کے معنے ہیں کہ میرا ہاتھ لمبا ہوا اور بڑھا.اَلرِّیْحُ ھَبَّتْ.ہوا چلی.اَلنَّاقَۃُ بِرَاکِبِھَا.اَسْرَعَتْ.اونٹنی اپنے سوار کو لے کر تیزی سے چلی.اَلشَّیْءُ ھَوِیًّا وَھُوِیًّا.سَقَطَ مِنْ عُلُوٍّ اِلٰی اَسْفَلَ.کوئی چیز اوپر سے نیچے کو گری (اقرب) پس تَھْوِیْ اِلَیْھِمْ کے معنے ہوں گے (۱) کہ لوگوں کے دل اُن کی طرف شوق سے بڑھیں.(۲) ایسے مائل ہوں جیسے کوئی چیز گر کر تیزی سے آتی ہے.(۳) ان کے دل ہر وقت ان کی طرف مائل رہیں.اَلثَّمَرَاتُ.الثَّمَرَۃُ.حِمْلُ الشَّجَرِ.درخت کا پھل.اَلنَّسْلُ.نسل.الْوَلَدُ.لڑکا.اَلثَّمَرَۃُ مِنَ اللِّسَانِ طَرَفُہٗ وَعَذَ بَتُہٗ.زبان کی نوک.یعنی عمدہ کلام.ثَـمَرَۃُ الْقَلْبِ.اَلْمَوَدَّۃُ.دوستی.خُلُوْصُ الْعَھْدِ.خالص عہد.پس وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ کے معنے ہوں گے (۱) کہ ان کو ظاہری پھلوں سے رزق عطا کر.(۲) ان کے خلوص دل سے کئے ہوئے اعمال ضائع نہ ہوں بلکہ پھل دار ہوں.(اقرب) تفسیر.حضرت ابراہیم کی اپنی نیت کو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا اس آیت میں حضرت ابراہیم اپنی نیت کو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کرکے اس کے فضل کو طلب کرتے ہیں.خدا تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے.وہ کبھی کسی اچھے عمل کو جو نیک نیتی سے کیا گیا ہو ضائع نہیں کرتا.پس وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں
Page 178
کہ تیری مقدس عبادت گاہ کی خدمت اور آبادی کے لئے میں نے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑا ہے اور اس نیت سے یہاں چھوڑا ہے کہ وہ تیرے ذکر کو بلند کریں اور یہ جانتے ہوئے چھوڑا ہے کہ اس جگہ دنیوی آرام کا کوئی سامان نہ موجود ہے نہ ہوسکتا ہے.پس اب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایک تو جس مقصد کے لئے میں نے ان کو یہاں رکھا ہے وہ پورا ہو.لوگ ان کی طرف توجہ کریں اور ان کی تبلیغ اور ان کے وعظ میں اثر ہو اور یہ تیری عبادت قائم کرنے میں کامیاب ہوں.دوسرے ان کی جسمانی حالت کی درستی کا بھی خیال رکھ.اور باوجود اس کے کہ انہیں میں ایسے علاقہ میں چھوڑ رہا ہوں کہ گھاس کی پتی بھی وہاں نظر نہیں آتی تو اعلیٰ سے اعلیٰ پھل بھی ان تک پہنچا.تاکہ انہیں معلوم ہوجائے کہ جو خدا تعالیٰ کے لئے قربانی کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ضائع نہیں کرتا.حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر اس دعا کا اثر دیکھو کتنا وسیع ہوا ہے.آج سب دنیا مکہ والے کے نام پر قربان ہے اور دل آپ ہی آپ اس کی تعلیم کی طرف جھکے جارہے ہیں اور اب تو مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے اور بھی ترقی کے سامان پیدا ہورہے ہیں.یہ تو دینی حصہ کی دعا کا حال ہے.باقی رہا دنیوی حصہ.سو وہ عجیب طرح پورا ہورہا ہے.اس بے آب و گیاہ علاقہ میں ہر قسم کے اور عمدہ سے عمدہ پھل میسر ہیں.میں نے ایسے اچھے انگور اور انار مکہ میں کھائے ہیں کہ نہ ہندوستان میں نہ شام میں نہ اٹلی اور فرانس میں ویسے نظر آئے.دنیا بھرکا پھل وہاں جاتا اور ابراہیمی دعا کی قبولیت کا ثبوت دیتا ہے.اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ میں من بعضیہ نہیں بلکہ زائدہ ہے اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ کے متعلق بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں من بعضیہ ہے یعنی کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوں.مگر یہ درست نہیں.دعا کرنے والا کبھی تھوڑی چیز نہیں مانگتا.پس یہاں من بعضیہ نہیں بلکہ زائدہ ہے.حروف زائدہ معنوں میں زور پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں حروف زائدہ تاکید کے لئے آتے ہیں یعنی وہ معنوں میں زور پیدا کر دیتے ہیں یعنی جومفہوم بغیر حروف زائدہ کے پیدا ہوتا تھا اس میں ان کے ذریعہ سے قوت اور طاقت پیدا کر دی جاتی ہے.چنانچہ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ میں سے مِنْ کو اڑا دیا جائے تو اَفْئِدَۃُ النَّاسِ رہ جائے گا اور اس کے معنے ’’لوگوں کے دل‘‘ کے ہوں گے.چونکہ ال خصوصیت اور کمال کے لئے بھی آتا ہے اور یہی اس جگہ مراد ہے.پس اس جملہ کے معنے ہوئے.’’ کامل اور خاص لوگوں کے دل‘‘ مِنْ نے داخل ہوکر ان معنوں میں اور زور پیدا کر دیا اور مراد یہ ہوئی کہ مکہ والوں کی طرف جھکنے والے دل نہایت پاک اور نہایت کامل لوگوں کے دل ہوں.
Page 179
یاد رکھنا چاہیے کہ حروف زائدہ سے مراد لغو اور بے کار اور زائد حروف نہیں بلکہ ان سے مراد معنوں میں زیادتی کرنے والے حروف ہیں اور اسی وجہ سے ان کے معنے تاکید کے ہوتے ہیں.وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ.ظاہری پھلوں کے علاوہ یہ مراد بھی ہوسکتی ہے کہ ان کی عبادات اور ان کی قربانیاں ضائع نہ ہوں بلکہ ان کے اعلیٰ نتائج نکلتے رہیں.حضرت ابراہیم کی یہ دعا حضرت نبی کریم ؐ کے وجود میں پوری ہوئی میرے نزدیک یہ دعا آنحضرت صلعم کے لئے ہے.آپؐ سے پہلےتَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ کا مفہوم کب پورا ہوا.آپؐ سے پہلے صرف عرب لوگ ہی مکہ جاتے تھے.مگر اب آنحضرت صلعم کے بعد تمام جہان کے لوگ وہاں دوڑے چلے جاتے ہیں.پس میرے نزدیک اس دعا میں ایسے رسول کی دعا کی گئی تھی جو سب دنیا کی طرف مبعوث ہو اور جس کی آواز کو سن کر سب دنیا کے لوگ مکہ میں حج کے لئے جمع ہوں اور مکہ کو توحید کا مرکز بنا کر شرک اور مشرکوں سے پاک کر دیا جائے.حضرت ابراہیم کے خواب کی تعبیر میرے نزدیک حضرت ابراہیمؑ نے جو یہ خواب میں دیکھا تھا کہ وہ حضرت اسمٰعیل ؑ کو ذبح کررہے ہیں اس کی تعبیر یہی تھی کہ وہ انہیں ایک دن ایک غیرذی زرع وادی میں چھوڑ جائیں گے.ایسی جگہ پر چھوڑنا ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح ہی کرنا تھا.حضرت ابراہیم نے زمانہ کے رواج کے مطابق اس کی تعبیر غلط سمجھی تھی.کیونکہ اس زمانہ میں لوگ انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے.انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا یہی منشاء ہے کہ حضرت اسمٰعیل ؑ کو ذبح کر دیا جائے لیکن دراصل اس کی تعبیر یہی تھی کہ وہ ان کو ایک غیرذی زرع وادی میں چھوڑیں گے.اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً ہی خواب کی تعبیر نہ سمجھائی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانی قربانی کا منسوخ قرار دینے والا بنائے.چنانچہ جب حضرت ابراہیم ؑ اپنی خواب کو لفظاً لفظاً پورا کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو اس نے انہیں بتا دیا کہ تمہارا اخلاص بھی ظاہر ہو گیا اور یہ حکم بھی قائم ہو گیا کہ آئندہ انسان کو بغیر جنگ یا بغیر قصاص کے قتل نہ کیا جائے گا.آئندہ انسانی قربانی بامعنی ہو گی.یعنی انسان اپنے وقت، اپنے علم، اپنے مال کو قربان کرکے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا نہ کہ اپنے گوشت کو قربان کرکے.پس تم ظاہر میں ردبلا کے طور پر بکرے کی قربانی کردو.اور حقیقت میں اپنے بچہ کی ایک تلخ قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ جو آئندہ پیش آنے والی ہے.
Page 180
رَبَّنَاۤ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَ مَا نُعْلِنُ١ؕ وَ مَا يَخْفٰى عَلَى اے ہمارے رب جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تو یقیناً (سب) جانتا ہے اور اللہ (تعالیٰ) سے اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ۰۰۳۹ کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہ سکتی ہے اور نہ آسمان میں تفسیر.حضرت ابراہیم ؑ نے حضرت اسمعیل ؑ کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے جنگل میں چھوڑا اس آیت میں بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم ؑ کا یہ فعل نہایت نیک نیت کی بناء پر تھا.ضمناً اس میں بائبل کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے.بائبل میں ہے کہ حضرت سارہؓ ناراض ہوگئی تھیں.اس لئے ان کو خوش کرنے کے لئے حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمٰعیلؑ اور ان کی والدہ کو جنگل میں چھوڑا تھا(پیدائش باب ۲۱ آیت ۸ تا ۱۲).یعنی ایک نبی نے اپنی ایک بیوی کی رضامندی کے لئے بعض بے گناہوں پر ظلم کیا.قرآن کریم اس امر کا جو حضرت ابراہیم کے نام پر دھبہ ہے خود حضرت ابراہیم کے منہ سے دفعیہ کرواتا ہے اور ان کی مذکورہ بالا دعا نقل کرکے بتاتا ہے کہ یہ بیان بائبل کا غلط اور بے بنیاد ہے.اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے رب! تو تو جانتا ہے کہ میری نیت ان کو جنگل میں چھوڑنے سے کیا ہے؟ میں ایسا کسی دنیوی غرض کی وجہ سے نہیں کررہا.بلکہ محض تیری خوشنودی کے حصول کے لئے اپنے بیوی بچوں کو اس جنگل میں چھوڑے جارہا ہوں.مَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ میں مِنْ کا جو لفظ آیا ہے اس کا مفہوم اس جگہ ’’بھی‘‘ کے لفظ سے ملتا ہے.یعنی کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس فقرہ کو اس لئے دوہرایا ہے کہ جس طرح ابراہیمؑ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ! تو میری نیت کو خوب جانتا ہے اسی طرح اللہ نے بھی ان کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ مَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ.بے شک ہم بھی اس کی نیت سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا یہ فعل بیوی کی رضا حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہماری رضا حاصل کرنے کے لئے تھا.
Page 181
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَ ہر ایک(قسم کی) تعریف اللہ (تعالیٰ ہی) کے لئے (مخصوص) ہے (وہ اللہ) جس نے (میرے) بڑھاپے کے اِسْحٰقَ١ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ۰۰۴۰ باوجود مجھے(دو بیٹے) اسمعیل اور اسحاق عطا کئے ہیں.میرا رب یقیناً خوب (ہی) دعائیں سننے والا ہے حل لغات.وَھَبَ لَہٗ مَالًا.اَعْطَاہُ اِیَّاہُ بِلَا عَوَضٍ.بغیر بدلہ کے اُسے مال دیا.(اقرب) تفسیر.جیسا کہ اوپر کی آیات سے ظاہر ہے اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے اس حصہ کا ذکر ہے جبکہ وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے.کیونکہ جو دعائیں اس جگہ مذکور ہیں وہ اس وقت کی ہیں (دیکھو سورۃ بقرہ ع ۱۵/۱۵) اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الحمد للہ کہنے کا مطلب اس پر کہا جاسکتا ہے کہ پھر اس موقعہ پر اولاد کے ملنے کا ذکر اور اس پر الحمدللہ کہنے سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا موقع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر اولاد کے ملنے پر الحمدللہ نہیں کہہ رہے بلکہ اس بات پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں عبادت قائم کرنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں.ان کو محض اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ذریعہ سے خدا کی عبادت کی بنیاد رکھ چلے ہیں.اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق ؑ بھی وقف تھے کیونکہ ان کو بھی دعا میں شامل کیا ہے.ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا یہ آیت ایک بے مثل ثبوت پیش کرتی ہے.بڑھاپے کی ا ولاد بڑا لڑکا بے آب و گیاہ جنگل میں چھوڑ کر آئے ہیں.جہاں میٹھے پانی اور خوراک تک کا پہنچنا مشکل ہے.لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اس قدر یقین ہے کہ جب دنیا کی نگاہ میں انہوں نے اپنے بیٹے کے مستقبل کو تباہ کر دیا وہ نہایت جوش و خروش سے اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں لگے ہوئے ہیں کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے.جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیئے اور ان کے حق میں میری دعاؤں کو سنا.گویا انہیں اس بڑھاپے میں بھی اولاد کی خواہش تھی تو صرف اس لئے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو اور اس کے دین کو دنیا میں قائم کرے.سو اسمٰعیل کی قربانی سے یہ مقصد پورا ہو گیا.اپنے پیارے اور بڑے بیٹے کو اس طرح جنگل میں چھوڑ دینے کے بعد جبکہ خطرات سامنے نظر آرہے تھے اولاد کی پیدائش اور کامیاب زندگی پر خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا صرف ابراہیمؑ اور اس کی قسم
Page 182
کے لوگوں کا ہی کام ہے.اَللَّھُمَّ صَلِّ عَلَیْھِمْ وَارْفَعْ دَرَجَاتِھِمْ.رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ١ۖۗ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ (اے) میرے رب مجھے اور میری اولا د میں سے (ہر ایک کو)نماز کو عمدگی سے ادا کرنے والا بنا (اے )ہمارے دُعَآءِ۰۰۴۱ رب(مجھ پر فضل کر) اور میری دعا (پوری طرح) قبول فرما حل لغات.مُقِیْمُ الصَّلٰوۃِ مُقِیْمٌ اَقَامَ سے اسم فاعل ہے جو قَامَ کا مجرد ہے.کہتے ہیں قَامَ الْاَمْرُ.اِعْتَدَلَ.معاملہ درست ہو گیا.عَلَی الْاَمْرِ.دَامَ وَثَبَتَ یعنی کسی چیز پر دوام اور ثبات اختیار کیا اور قَامَ السُّوْقُ کے معنے ہیں نَفَقَتْ.بازار بارونق ہو گیا اور اَقَامَ الصَّلٰوۃَ کے معنے ہیں اَدَامَ فِعْلَھَا.نماز پر دوام اختیار کیا.اَقَامَ لِلصَّلٰوۃِ کے معنے ہیں نَادٰی لَھَا.نماز کے لئے پکارا.اَقَامَ اللہُ السُّوْقَ جَعَلَھَا نَافِقَۃً.بازار کو بارونق بنا دیا.(اقرب) پس رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ کے معنے ہوں گے کہ ہمیں ایسا بنا دے کہ نماز کا رواج دینے والے ہوں.اور لوگوں کو اس طرف لانے والے ہوں اور نماز کی طرف لوگوں کو پکارنے والے ہوں.تفسیر.حضرت ابراہیم کا اِقَامةِ صَلوٰة کی دعا کرنے کا مطلب حضرت ابراہیمؑ نبوت کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور اولاد بھی ہوچکی ہے.پھر وہ جوان ہے اور پھر اس کو دین کے لئے وقف بھی کر چکے ہیں.پھر کیوں کہتے ہیں رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ.کیا آپ کو اس بات میں کہ آپ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے کوئی شبہ تھا.اس سے آپ کی مراد یہ نہ تھی کہ میں نماز کو قائم نہ رکھ سکوں گا بلکہ ا س طرف اشارہ تھا کہ میرے ذریعہ اور میری اولاد کے ذریعہ سے دنیا میں نماز قائم رہے.اِقَامةِ صَلٰوة شخصی بھی ہو سکتی ہے اور قومی بھی.اس جگہ قومی اِقَامةِ صَلٰوة مراد ہے اِقَامَۃُ الصَّلٰوۃ شخصی بھی ہوسکتی ہے اور قومی بھی.اس جگہ قومی مراد ہے اور حضرت ابراہیم کی دعا کا یہ مطلب ہے کہ میری کوششوں میں ایسا اثر دے کہ ہمیشہ میرے ذریعہ سے ایک نمازگذاروں کی جماعت قائم رہے اور اسی طرح میری اولاد میں سے بھی ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے رہیں جو میرا ہاتھ بٹاتے رہیں اور لوگوں کو عبادت الٰہیہ کی طرف لاتے رہیں اور وہ بھی اپنی کوششوں میں کامیاب رہیں.اس طرح تاقیامت میں نمازوں کا قائم رکھنے والا بن جاؤں.یہ مقام
Page 183
عام مُقِیْمُ الصَّلٰوۃِ سے بہت بڑھ کر ہے کیونکہ وہ شخص صرف اپنی نماز کو قائم کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کی نماز قائم کرنے کے لئے دعا کررہے ہیں.حضرت نبی کریم ؐ کے متعلق دعا اور پیشگوئی دراصل یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دعا اور پیشگوئی ہے کہ جس طرح میرے ذریعہ سے نمازیں قائم ہوئی ہیں اسی طرح آئندہ بھی میری اولاد سے ایک شخص نمازوں کا قائم کرنے والا پیدا ہو.رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ (اے ) ہمارے رب جس دن حساب ہونے لگے اس دن مجھے اور میرے والدین کو الْحِسَابُؒ۰۰۴۲ اور تمام مومنوں کو بخش دیجئیو حلّ لُغَات.غَفَرَ اِغْفِرْلِیْ غَفَرَ الشَّیْءَ غَفْرًا کے معنے ہیں سَتَرَہٗ.اس کو ڈھانپ لیا.الْمَتَاعَ فِی الْوِعَاءِ: اَدْخَلَہٗ وَسَتَرَہٗ.سامان کو برتن میں داخل کیا اور اس کو ڈھانپ دیا.الشَّیْبَ بِالْخِضَابِ.غَطَّاہُ سفید بالوں کو خضاب سے ڈھانپا.اللہُ لَہٗ ذَنْبَہٗ غَفْرًا غَطَّی عَلَیْہِ گناہوں پر پردہ ڈالا.اَلْاَمْر بِغُفْرَتِہٖ.اَصْلَحَہٗ بِمَا یَنْبَغِی اَنْ یُّصْلَحَ بِہٖ.معاملہ کی اصلاح مناسب طریقہ سے کی.(اقرب) پس غَفَرَ کے لفظ میں ڈھانپنے کے معنے پائے جاتے ہیں اور اِغْفِرْلِیْ کے معنے ہوں گے (۱) مجھے ڈھانپ لے.مجھ پر پردہ ڈال دے.یعنی میرا وجود مٹا کر اپنا وجود میرے ذریعہ سے ظاہر کر.(۲) میری بشریت کو الوہیت کی چادر سے ڈھانپ لے.یعنی میری کوششوں کے نتائج تیری شان کے مطابق نکلیں.(۳) میرے تمام کاموں کی عمدہ طریقوں سے اصلاح فرمادے.یعنی میرے تمام کام درست ہو جائیں.اور میری اولاد کی کمزوریوں کو ڈھانپ کر ان کو ترقی کے منازل کی طرف لے جا.تفسیر.انبیاء کے استغفار کرنے کا مطلب نبی خدا کے فضل سے معصوم ہوتا ہے پھر نبی کا یہ کہنا کہ اِغْفِرْلِی اس کا کیا مطلب؟دراصل غیر عارف انسان کی نظر محدود ہوتی ہے.اس کی نظر انسان تک ہی جاتی ہے اور انسان تک ہی تسلی پا جاتی ہے مگر عارف کی نظر اوپر جاتی ہے اور بلند ہوتی جاتی ہے.وہ سمجھ لیتا ہے کہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کیا ہستی ہے.سورج کے سامنے ایک ذرہ کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ آخر انسان اسی کی مخلوق
Page 184
ہے.اس کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے اور ہدایت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے.غالب نے کیا ہی عمدہ کہا ہے ؎ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اِغْفِرْلِیْ سے مراد پس نبی چونکہ عارف ہوتا ہے وہ اپنی ہستی کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ میں کررہا ہوں وہ میں نہیں بلکہ خدا ہی کر رہا ہے.اس لئے وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! میرے وجود کو زیادہ سے زیادہ مخفی کر دے اور اپنے وجود کو زیادہ سے زیادہ ظاہر فرما.گویا اِغْفِرْلِیْ کے اس صورت میں یہ معنے ہوتے ہیں کہ اے خدا! تجھے میری ہی محبت کا واسطہ ہے کہ اپنا پردہ مجھ پر ڈال دے.یعنی میرا وجود مٹا کر تیرا وجود میرے ذریعہ سے ظاہر ہونے لگے اور یہ امر ظاہر ہے کہ بندہ کے ذریعہ سے جس قدر اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر ہوگا اسی قدر وہ اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہوگا.غَفَر کے لفظ کے معنے حسب مراتب ہوتے ہیں ہاں جب دوسروں کے لئے یہ لفظ آئے تو اس وقت ان کے حسب مراتب اس لفظ کے معنے ہوں گے.ایک اعلیٰ درجہ کا مومن یہ لفظ استعمال کرے گا تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ کمزوریاں جو حصولِ کمال سے محروم کرتی ہیں ان سے مجھے بچا لے.درمیانی درجہ کے مومن کے لئے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ میری خطاؤں کو ڈھانپ کر مجھے اعلیٰ ترقیات کی توفیق دے اور عام مومن یہ لفظ استعمال کرے تو یہ مطلب ہوگا کہ میرے قدم کو ایمان پر استقلال سے قائم رکھ.میرے گناہ مجھے کہیں لے نہ ڈوبیں اور ایک متلاشی حق یہ لفظ استعمال کرے تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ میرے گناہ مجھے ہدایت پانے سے محروم نہ کر دیں.اس لئے میرے گناہ معاف کر.اس لفظ کا استعمال مختلف مواقع کے لحاظ سے ایسا ہی ہے جیسے جبار کا لفظ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لئے آتا ہے تو اس کے معنے مصلح کے ہوتے ہیں اور جب یہی لفظ بندے کے لئے آتا ہے تو اس کے معنے سرکش اور قانون شکن کے ہوتے ہیں.یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی نسبت فرماتا ہے اللّٰهُ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهٖ(آل عمران :۱۸۰).تو جب اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے تو پھر ان میں گناہ کہاں سے آسکتا ہے؟ جب وہ دنیا سے الگ کرکے خدا تعالیٰ کے قرب میں بٹھا دئیے گئے تو پھر ان کے پاس شیطان کہاں سے آئے گا؟ شیطان تو خدا تعالیٰ کے نام سے بھی بھاگتا ہے.شیطان کا تسلّط اللہ کے بندوں پر نہیں ہوتا اسی طرح دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ(الحجر:۴۳).میرے بندوں پر یقیناً تجھے کوئی تسلط حاصل نہیں.پس جب قانون یہ ہے کہ جو ادنیٰ عبودیت
Page 185
کے مقام پر ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتا ہے تو انبیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں ان کے پاس شیطان کا گذر کیسے ہوسکتا ہے؟ آیت یوم الحساب والی دعا کا مطلب يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.یہ حساب اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اگلے جہان میں بھی ہوگا.دعا کا مطلب یہ ہے کہ جب اعمال کے نتیجے نکلنے لگیں اس وقت میری بشریت کو الوہیت کی چادر سے ڈھانپ لینا.میری بشری کمزوری پر پردہ ڈالنا.میری کوششوں کے نتائج میری طاقتوں کے مطابق نہ نکلیں بلکہ تیری شان کے مطابق نکلیں.اگر قیامت کا دن مراد لیا جائے تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ اس دن مجھ سے وہ سلوک کیجئیو جو تیری شان کے مطابق ہو نہ کہ وہ جو میرے اعمال کے مطابق ہو اور میرے والدین اور مومنوں سے بھی ان کے درجہ کے مطابق غفران کا معاملہ کیجئیو.وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ١ؕ۬ اِنَّمَا اور(اے مخاطب)یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے تو اللہ (تعالیٰ) کو بے خبر ہرگز نہ سمجھ.يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُۙ۰۰۴۳ وہ انہیں صرف اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن (ان کی ) آنکھیں(فیصلہ کے انتظار میں )کھلی ہوئی ہوںگی حلّ لُغَات.تَشْخَصُ.شَخَصَ سے مضارع ہے.شَخَصَ الشَّیْءُ شَخُوْصًا کے معنی ہیں اِرْتَفَعَ بلند ہوئی.شَخَصَ بَصَرُہٗ: فَتَحَ عَیْنَیْہِ وَجَعَلَ لَا یَطْرِفُ مَعَ دَوْرَانٍ فِی الشَّحْمَۃِ.اور شَخَصَ بَصَرَہٗ کے معنے ہیں اپنی آنکھوں کو کھولا اور ایک جگہ ٹکٹکی لگا کر دیکھنا شروع کر دیا اور کسی اور طرف نہ دیکھ سکا.اَلمَیِّتُ بَصَرَہٗ وَبِبَصَرِہٖ.میت نے جان کندن کے وقت نظر اوپر اٹھا لی.شَخَصَ مِنْ بَلَدٍ اِلٰی بَلَدٍ.ایک شہر سے دوسرے شہر کو گیا.اَلرَّجُلُ سَارَ فِیْ ارْتِفَاعٍ بلندی کی طرف چڑھا شَخَصَ السَّہْمُ.اِرْتَفَعَ عَنِ الْھَدَفِ.تیر نشانہ پر نہ لگا.(اقرب) پس تَشْخَصُ فِیْہِ الْاَبْصَارُ.کے معنے ہوں گے کہ اس دن ان کی آنکھیں اوپر اٹھیں گی.(۲) نظریں چڑھ جائیں گی.(۳) پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی.وہ آنکھ جھپک نہیں سکیں گے.وَ لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ اور تو ہرگز اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھ اس سے جو ظالم کرتے ہیں.یا ان کے عمل سے.غافل کے یہ معنی نہیں کہ واقف نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھوکہ ان کو جب اللہ تعالیٰ سزا
Page 186
نہیں دیتا تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے.غافل دو طرح ہوسکتا ہے.(۱) بے خبری سے (۲) توجہ نہ کرنے سے.تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے سزا نہیں چھوڑے گا.اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ صرف ان کو ڈھیل دے رہا ہے اس دن کے لئے کہ جس دن لوگوں کی نظریں چڑھ جائیں گی.یا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ آنکھ نہیں جھپک سکیں گے.جب انسان پر حیرت کا وقت آتا ہے تو وہ آنکھ جھپک نہیں سکتا.مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ ان کو درمیانی ڈھیل دے رہا ہے.اس دن تک جس دن ان پر آخری عذاب آئے گا.اس وقت تک ان کو ڈھیل دے گا.(اس آیت کی تفسیر اگلی آیت کے ساتھ دیکھیں.) مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ (وہ) اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے خوف زدہ ہو کر دوڑتے آرہے ہوں گے(اور ) ان کی نظریں (لوٹ کر) طَرْفُهُمْ١ۚ وَ اَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌؕ۰۰۴۴ واپس نہیں آئیں گی اور ان کے دل (امیدوں سے )خالی ہوں گے.حل لغات.مُھْطِعِیْنَ- اَھْطَعَ سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے.جس کا مجرد ھَطَعَ ہے.کہتے ہیں ھَطَعَ الرَّجُلُ اَسْرَعَ مُقْبِلًا خَائِفًا.خوف زدہ ہو کر تیزی سے دوڑتا ہوا آیا.اَقْبَلَ بِبَصَرِہٖ عَلَی الشَّیْءِ فَلَمْ یَرْفَعْہُ عَنْہُ.کسی چیز پر ٹکٹکی لگا کر دیکھتا رہا.اور وہاں سے نظر کو نہ ہٹایا.اور اَھْطَعَ البَعِیْرُ کے معنی ہیں مَدَّ عُنُقَہٗ وَصَوَّبَ رَاْسَہٗ.اونٹ نے گردن کو لمبا کیا.ا ور سر کو اٹھایا.اَسْرَعَ وَاَقْبَلَ مُسْرِعًا خَائِفًا لَایَکُونُ اِلَّا مَعَ خَوْفٍ.اور اَھْطَعَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں خوف زدہ ہوکر جلدی سے آیا.(خوف کا ہونا ضروری ہے) وَقِیْلَ نَظَر بِخُضُوْعٍ.اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنے عاجزی کی نظر سے دیکھنے کے ہیں.(اقرب) پس مُھْطِعٌ کے معنے ہوں گے (۱) خوف زدہ ہوکر دوڑنے والا.(۲) عاجزی سے دیکھنے والا.(۳) سر اوپر اٹھانے والا.مُھْطِعِیْنَ اس کی جمع ہے.مُقْنِعٌ مُقْنِعِیْ رُؤُوْسِھِمْ: اَقْنَعَ رَأْسَہٗ نَصَبَہٗ سر کو سیدھا اٹھایا.وَقِیْلَ لَا یَلْتَفِتُ یَمِیْنًا وَشِمَالًا وَ جَعَلَ طَرَفَہٗ مُوَازِیًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ اور بعض نے اَقْنَعَ کے یہ معنے کئے ہیں کہ اپنے سر کو اٹھا کر بالکل سیدھا رکھے اور دائیں بائیں نہ موڑے.اَقْنَعَ الصَّبِیَّ کے معنے ہیں وَضَعَ اِحْدَی یَدَیْہِ عَلٰی فَأْسِ قَفَاہُ وَجَعَلَ الْاُخْرٰی
Page 187
َحْتَ ذَقَنِہٖ وَاَمَالَہٗ اِلَیْہِ فَقَبَّلَہٗ.بچے کے سر کے پچھلی طرف ہاتھ رکھ کر اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اسے اپنی طرف پھیرا اور اسے بوسہ دیا.اَقْنَعَ حَلْقَہٗ وَفَمَہٗ.رَفَعَہُ لِاسْتِیْفَاءِ مَا یَشْرَبُہٗ مِنْ مَّاءٍ اَوْلَبَنٍ اَوْغَیْرِھِمَا.اس نے اپنے منہ کو اونچا کیا تاکہ پانی وغیرہ پوری طرح پی سکے.بِیَدَیْہِ فِی الصَّلَوۃِ رَفَعَھُمَا فِی الْقُنُوْتِ.اپنے ہاتھوں کو نماز میں قنوت کے لئے اٹھایا.رَأْسَہٗ وَعُنُقَہٗ رَفَعَہٗ وَشَخَصَ بِبَصَرِہٖ نَحْوَالشَّیْءِ لَایَصْرِفُہٗ عَنْہُ.اپنے سر کو اٹھایاا ور نظر ایسے طور پر کسی چیز پر جمائی کہ اس سے ہٹ نہ سکے.(اقرب) مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ میں ان کی حیرانگی اور خوف زدہ ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے.کہ ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے سر بلند کرکے آنحضرتؐ کے لشکر کو دیکھ رہے ہوں گے.ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی.اور وہ سخت خوفزدہ ہو کر بھاگیں گے.اَلْھَوَآءُ.اَلشَّیءُ الْخَالِیُ.خالی چیز.اَلْـجَبَانُ لخِلُوِّ قَلْبِہٖ عَنِ الْجُرْأَۃِ.بزدل پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے.کیونکہ اس کا دل جرأت سے خالی ہوتا ہے.(اقرب) وَاَفْئِدَتُـھُمْ ھَوَاءٌ.ان کے دل امیدوں سے خالی ہوں گے.ان کے دل بیٹھے جارہے ہوں گے.بزدلی ان پر چھائی ہوگی اور مقابلہ نہ کرسکیں گے.تفسیر.کفار کو ڈھیل حضرت ابراہیم ؑ کی دعا سے مل رہی تھی یہ بتا کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے نبی کے لئے دعا کی تھی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو قائم کرے.مکہ اس کا مرکز ہو اور شرک سے اس کی تعلیم پاک ہو اب اللہ تعالیٰ کفار مکہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ بے شک ان کو ڈھیل ملی ہے لیکن اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم ان کے اعمال سے ناواقف ہیں بلکہ اس کی وجہ اور ہے.اس وجہ کو لفظاً اس جگہ نہیں بتایا کیونکہ اوپر کے رکوع سے وہ وجہ ظاہر ہو چکی ہے اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب !اگر میری اولاد مشرک ہو تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں.ہاں! آپ بڑے بخشنے والے مہربان وجود ہیں.اگر ان سے ترقی کا برتاؤ کریں تو آپ کی شان کے مطابق ہے.یہ دعا علاوہ ان کی ہدایت کی خواہش کے اس ڈھیل کا موجب ہورہی تھی مگر جو لوگ ازلی شقی تھے وہ اس سے الٹے مغرور ہورہے تھے.لیکن کب تک انہیں ڈھیل دی جاسکتی تھی.ایک دن اصل دعا اپنا رنگ لائے گی اور مہلت سزا میں بدل جائے گی.اس جملہ کو عَمَّا يَفْعَلُ الظّٰلِمُوْنَ سے ختم کیا ہے.یہ نہیں کہا کہ جو تیرے مخالف کرتے ہیں یا مکہ والے کرتے ہیں اس سے اول یہ بتانا مطلوب ہے کہ خواہ کتنی ہی ڈھیل ملے ظالم آخر اپنے کیفر کردار کو پہنچ کر ہی رہے گا.دوم محمد رسول اللہ صلعم اور صحابہؓ کے دل کو تسلی دینا مقصود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کررہے ہیں.ہم عدم توجہ کی وجہ سے ان کی طرف سے غافل نہیں ہیں.مسلمانوں کے مظلوم ہونے کا خیال ہے لیکن ابراہیمؑ
Page 188
کی وہ دعا کہ اے اللہ !میں تجھ سے بھی امید کرتا ہوں کہ میری اولاد غلطی کرے تو تو ان سے غفور رحیم کا سلوک کرے گا.ہمیں عذاب میں جلدی کرنے سے روک رہی ہے.آنحضرت ؐ کے منکرین پر عذاب کی خبر اس اظہار کے بعد کہ کیوں عذاب میں دیر ہوری ہے؟ عذاب کی خبر بھی دے دی اور اس کے متعلق بعض حالات بھی اشارۃً بتا دیئے یعنی وہ یکدم آئے گا.یہ لوگ سخت گھبرا جائیں گے.حیرت سے سر اٹھا کر عذاب کو دیکھیں گے.نظر کو ادھر ادھر نہ ہٹا سکیں گے.دل گر رہے ہوں گے.مکہ میں لشکر اسلام کا داخل ہونا جب مکہ فتح ہوا تو بعینہٖ یہی حال کفار کا ہوا.جب صلح حدیبیہ کے بعد مکہ والوں نے عہدشکنی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تو آپ نے ایسا انتظام فرمایا کہ کسی کو علم نہ ہوا کہ اسلامی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوا ہے.ابوسفیان دو دن پہلے ہی مدینہ سے روانہ ہوا تھا.جہاں سے وہ ایک ناکام سفیر کی حالت میں لوٹا تھا.ابھی وہ مکہ میں داخل نہ ہوا تھا کہ اسلامی لشکر جلد جلد منزلیں طے کرتا ہوا مکہ کے قریب پہنچ گیا.ابوسفیان ا ور اس کے ساتھیوں نے دور سے جب لشکر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ کبھی کہتے فلاں قبیلہ ہے اور کبھی کہتے فلاں ہے.انہیں یہ خیال ہی نہ آتا تھا کہ یہ لشکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوسکتا ہے.چنانچہ جب طلائع (یعنی لشکر کے آگے چلنے والا حصہ) آئے تو ان کو پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں.تب وہ حیران رہ گئے.ابو سفیان کاآنحضرت ؐ کی صداقت کو دیکھ کر ایمان لانا وہ حیران کھڑے تھے کہ حضرت عباسؓ نظر آئے.وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آئے (وہ بچپن سے اس کے دوست تھے) دیکھتے ہی کہا ابوسفیان! میرے پیچھے سوار ہو جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے.اس نے لیت و لعل کرنی چاہی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنے پیچھے گھوڑے پر چڑھا لیا اور ان کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے.آپ کے خیمہ کے پاس پہنچ کر زور سے ابوسفیان کو دھکا دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے.ابوسفیان گھبرا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے.حضرت عباسؓ نے ابوسفیان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کہا ابھی اپنے دین کا جھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہوا؟ ہلاکت میں مت پڑ اور مسلمان ہو جا.اور ابوسفیان کا ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا.آپ نے اس خیال سے کہ شاید یہ حضرت عباسؓ کے کہنے پر بیعت کرنا چاہتا ہے کچھ تردد کیا.لیکن جب اسے مصر دیکھا اس کی بیعت لے لی.ابوسفیان نے کہا یا رسول اللہ! میں اب مسلمان ہوا ہوں.مکہ والوں کا سردار ہوں.مجھے کچھ اعزاز دیا جائے.آپ نے فرمایا جو تمہارے گھر میں داخل ہوگا اسے امان دی جائے
Page 189
گی.اس نے کہا میرا گھر بہت چھوٹا ہے.فرمایا جو کعبہ میں داخل ہو اسے امان دی جائے گی.اس نے کہا وہ بھی چھوٹا ہے.آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرلے گا اسے امان دی جائے گی.ابوسفیان نے کہا بس! اب ٹھیک ہے اور دوڑ کر مکہ والوں کو آپ کے حملہ آور ہونے اور مذکورہ بالا امان دینے کا اعلان کیا(السیرة الحلبیة).مکہ والے جو اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ طاقتور سمجھتے تھے ان کے دلوں کی اس وقت کی حالت کا اندازہ کرنا آسان کام نہیں.اپنی حکومت کو پائیدار اور غیر متزلزل سمجھنے والوں نے جب اپنے سردار کے منہ سے جو ایک نیا معاہدہ کرنے مدینہ گیا تھا یہ اعلان سنا ہوگا کہ مکہ والو! اپنے اپنے گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لو کہ محمد (رسول اللہ) جسے تم نے دس سال پہلے تنہا مکہ سے نکالا تھا اس کا عظیم الشان لشکر چند فرسنگ پر سرعت سے مکہ کی طرف کو رخ کئے چلا آ رہا ہے.اس لئے فوراً اپنے دروازوں کو بند کرکے بیٹھ جاؤ کہ اب اس سے تمہارے لئے کوئی امان کی صورت نہیں.تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ یقیناً ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوں گی.ان کے سر بلند ہوہو کر اس راستہ کو دیکھ رہے ہوں گے جس پر سے اسلامی لشکر بڑھا چلا آ رہا تھا اور دنیا کا اور کوئی مسئلہ ان کی توجہ کو اپنی طرف نہ کھینچ سکتا ہوگا.اور ان کے دل اندر ہی اندر بیٹھے جاتے ہوں گے.جب وہ دروازے بند کرکے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہوں گے اور جھروکوں اور کواڑوں کے سوراخوں سے اسلامی لشکر کو مکہ کی گلیوں میں کوچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے ان کی اس وقت کیا حالت ہو گی؟ اس کا نقشہ ان قرآنی الفاظ سے زیادہ اور کون سے الفاظ کھینچ سکتے ہیں.مکہ میں آنحضرت ؐ کا لشکر داخل ہونے کے وقت اہل مکہ کی حالت مکہ والوں کے لئے کیسی تلخی تھی؟ اس خیال میں کہ وہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) جسے انہوں نے تاریکی میں جب کہ سب مکہ کے دروازے بند تھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اب دن کے وقت مکہ میں داخل ہو رہا تھا.اور اب بھی مکہ کے دروازے بند تھے.وہ دروازے جو ہجرت کے دن اس لئے بند تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں پناہ نہیں مل سکتی تھی فتح مکہ کے دن اس لئے بند تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذریعہ سے مکہ والوں کو پناہ دی تھی.اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ.کفار کو آنحضرت ؐ کے لشکر کی آمد کا پتہ نہ ملنا خدا ئی تصرف تھا یہ صرف خدائی تصرف تھا کہ آپ کے آنے کا مکہ والوں کو پتہ نہ لگا حالانکہ آپ اس راستہ سے آئے تھے جو آمدورفت کا ایک عام راستہ تھا جہاں سے مکہ والوں کو فوراً خبر پہنچ سکتی تھی لیکن ان کو خبر نہ ہوئی اور اس طرح یہ پیشگوئی پوری ہوئی.
Page 190
وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اور تو لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر وہ (موعود ) عذاب آئے گا اور جن لوگوں نے ظلم (کا شیوہ اختیار) کیا ہوگا ظَلَمُوْا رَبَّنَاۤ اَخِّرْنَاۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ١ۙ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَ (اس وقت) کہیں گے( کہ اے )ہمارے رب ہمارے معاملہ کو کسی (اور ) قریب میعاد تک(کے لئے ) پیچھے ڈال نَتَّبِعِ الرُّسُلَ١ؕ اَوَ لَمْ تَكُوْنُوْۤا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ دے.ہم تیری (طرف سے آئی ہوئی) دعوت کو قبول کریں گے اور (تیرے)رسولوں کی پیروی کریں گے (جس پر مِّنْ زَوَالٍۙ۰۰۴۵ انہیںجواب ملے گاکہ کیا( ابھی اتمام حجت کی کوئی کسر باقی ہے ) اور کیا تم نے پہلے قسم (پر قسم ) نہیں کھائی تھی کہ تم پر کسی قسم کا زوال نہیں (آئے گا ) تفسیر.یہ اُخروی عذاب کا ذکر ہے.جہاں بھی قرآن کریم میں دنیوی عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آخرت کے عذاب کا بھی ضرور بیان ہوتا ہے کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے لئے دلیل ہوتا ہے.وَّ سَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ حالانکہ تم نےان لوگوں کے گھروں کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے جنہوں نے (تم سے پہلے ) اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر یہ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ۰۰۴۶ بات خوب روشن ہو چکی تھی.کہ ان کے ساتھ ہم نے کیسا معاملہ کیا تھا اور ہم تمام باتیں تمہارے لئے کھول کر بیان کر چکے ہیں.حل لغات.ضَرَبْنَا لَکُمُ الْاَمْثَالَ تمہارے لئے ضروری امور کھول کر بیان کر چکے ہیں.دیکھو ابراہیم آیت نمبر۲۵.
Page 191
تفسیر.اکثر قومیں ان علاقوں میں بستی ہیں جہاں پہلے دوسری اقوام بس چکی ہیں اور باوجود طاقت و قوت کے الٰہی آواز کا انکار کرکے عذاب پاچکی ہیں مگر افسوس کہ پھر بھی لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کے عذاب کو خود چکھنا چاہتے ہیں.وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ١ؕ وَ اِنْ كَانَ اور یہ (لوگ) اپنی( ہر ایک) تدبیر عمل میں لاچکے ہیں اور ان کی( ہر) تدبیر اللہ( تعالیٰ) کے ہاں( لکھی ہوئی اور مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ۰۰۴۷ محفوظ) ہے( بھولی نہیں)اور گو ان کی تدبیر ایسی (ہی کیوں نہ )ہو کہ اس کے نتیجہ میں پہاڑ( بھی) اپنی جگہ سے ٹل جائیں (لیکن یہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے) حلّ لُغَات.اَلْجَبَلُ کے لئے دیکھو رعدآیت نمبر ۳۲.تفسیر.وَ قَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ.اور انہوں نے اپنی تدبیریں کی تھیں جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا.عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ کے دو معنے وَ عِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا مکر ہونے کے دو معنے ہیں.اول ہر تدبیر کا نتیجہ خدا تعالیٰ ہی نکالتا ہے.پس ان کے مکر نتیجہ خیز نہیں ہوسکتے.وہ ان کی تدبیروں کو ضائع کر دے گا.دوم.ان کا مکر خدا تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے یعنی یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے تو ضائع ہو گیا ہے لیکن خود ان کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے ضائع نہیں ہوا.خدا تعالیٰ کے پاس موجود ہے وہ اس کی سزا ضرور دے گا.مکرھم میں مکر کی اضافت مفعول کی طرف بھی ہو سکتی ہے مَکْرُھُمْ میں مکر کی اضافت مفعول کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے مکر کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی ہے اس کے پاس محفوظ ہے.اس صورت میں تقریر عبارت یوں ہوگی مَکْرُہُ الَّذِیْ یَمْکُرُبِھِمْ.وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ کے دو معنی وَ اِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ.ان
Page 193
يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَ السَّمٰوٰتُ وَ بَرَزُوْا (اور وہ دن ضرور آنے والا ہے) جس دن اس زمین کو زمین کے سوا (کچھ اور) بنا دیا جائے گا.اور آسمانوں کو بھی لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۰۰۴۹ (کسی اورصورت میں بدل دیا جائے گا) اور یہ (لوگ) اللہ (تعالیٰ) کے جو واحد (اور ہر ایک چیز پر )کامل غلبہ رکھنے والا ہے سامنے ہوں گے.بَرَزَ یَبْرُزُ بُرُوْزًا خَرَجَ نکل کر سامنے آیا.(اقرب) تفسیر.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے جہان کے نعماء اس دنیا کی نعمتوں سے بالکل الگ ہیں کیونکہ یہاں فرمایا ہے کہ زمین و آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان قائم کئے جائیں گے.اگر اگلے جہان بھی اسی قسم کے میوے وغیرہ ہونے تھے تو زمین و آسمان کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پس اس دنیا کی نعمتوں کو اس دنیا کی نعمتوں پر قیاس کرنا بالکل خلاف عقل ہے.وَ تَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِۚ۰۰۵۰ اور اس دن تو ان مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھے گا.حلّ لُغَات.مُقَرَّنِیْنَ- قُرِّنَتِ الْاَسَارٰی فِی الْجِبَالِ اَیْ جُمِعَتْ.قیدیوں کو رسیوں میں ملا کر اکٹھا باندھا گیا.وَشُدِّدَ لِکَثْرَۃٍ وَمِنْہُ مُقَرَّنِیْنَ فِی الْاَصْفَادِ.اور تشدید تکثیر اور مبالغہ کے لئے لائی جاتی ہے.جیسے قرآن مجید میں مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ میں مُقَرَّنِیْنَ تشدید کے ساتھ آیا ہے.(اقرب) اَلْاَصْفَادُ کا مفرد اَلصَّفَدُ ہے اور اَلصَّفَدُ کے معنے ہیں اَلْعَطَاءُ بخشش.اَلْوَثَاقُ.باندھنے کی چیز.زنجیر رسہ وغیرہ.تفسیر.رسوں میں باندھنے کا مطلب اس جگہ سوال ہوسکتا ہے کہ قیامت کے دن رسوں میں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگلے جہان کی زندگی اس جہان کی ظل ہوگی.چونکہ ان لوگوں نے یہاں پر بداعمال ایک دوسرے کی شہ اور مدد پر کئے تھے اس لئے اس کا نظارہ اس رنگ میں دکھایا جائے گا کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رسوں میں باندھا جائے گا.مطلب یہ کہ برا اتحاد طاقت اور عزت کا موجب نہیں ہوتا.بدی
Page 194
پر جو اتحاد ہو وہ کمزوری اور ذلت کا موجب ہوتا ہے لیکن نبیوں کے مخالف اسے نہیں سمجھ سکتے.اور تقویٰ کے خلاف جتھا بندی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس جتھابندی کے ذریعہ سے ہم طاقت اور عزت حاصل کررہے ہیں.حالانکہ بدی پر جتھابندی ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص قیدی کے ساتھ ہتھکڑی میں اپنے ہاتھ بھی بندھوا دے.بے شک قیدی پہلے ایک تھا پھر دو ہو جائیں گے لیکن اس سے طاقت زیادہ نہ ہوگی بلکہ کمزوری پیدا ہوگی کیونکہ دو آدمیوں کا ایک ہتھکڑی میں بندھنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے.اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کے دشمنوں کو زنجیروں میں اکٹھا باندھ کر آشکار کر ےگا اور انہیں بتائے گا کہ تمہارے جتھے ایسے ہی تھے جیسے قیدیوں کو اکٹھا ایک زنجیر میں باندھ دیا جائے.سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّ تَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُۙ۰۰۵۱ ان کے کرتے (گویا ) تارکول کے ہوں گے اور (دوزخ کی ) آگ ان کے مونہوں کو ڈھانپ رہی ہو گی حلّ لُغَات.سَرَابِیْلُہُمْ سَرَابِیْلُ سِرْبَالٌ کی جمع ہے.اَلسِّرَبَالُ الْقَمِیْصُ سِرْبَالٌ کے معنی ہیں قمیص.وَقِیْلَ اَلدِّرْعُ اور زرہ کو بھی سِرْبَال کہتے ہیں.وَقِیْلَ کُلُّ مَالُبِسَ اور بعض نے اسے عام رکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو پہنی جائے سِرْبَال ہے.(اقرب) اَلْقَطِرَانُ: سَیَّالٌ دُھْنِیٌّ یُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِ الْأَبْھَلِ وَالْاَرْزِ وَنَحْوَھُمَا (اقرب) قطران ایک قسم کا سیال تیل کی قسم کا مادہ ہوتا ہے جو سَرو یا دِیار وغیرہ درختوں سے نکالا جاتا ہے جس میں جل اٹھنے کا مادہ ہوتا ہے.تفسیر.اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ان کا لباس سوا آگ کے اور کچھ نہ ہوگا.یہ فقرہ ایسا ہی ہے جیسے کہہ دیں کہ مٹی کا تیل چھڑک کر انہیں جلا دیا جائے گا.لباس چونکہ حفاظت کے لئے ہوتا ہے اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ ان کا کوئی محافظ نہ ہوگا.بلکہ جن کو وہ محافظ سمجھتے تھے وہ پھر ان کے دشمن اور مخالف ثابت ہوں گے.جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہوں میں لکھا ہے کہ مشرک جن کو خدا بناتے ہیں قیامت کے دن وہ ان سے بیزاری ظاہر کریں گے.
Page 195
لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ (یہ اس لئے ہو گا) تا اللہ (تعالیٰ) ہر شخص کو جو کچھ اس نے (اپنے لئے) کیا ہوگا اس کا بدلہ دے.اللہ( تعالیٰ )یقیناً الْحِسَابِ۰۰۵۲ (بہت) جلد حساب لےلینے والا ہے.تفسیر.لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ یعنی جو اس نے اعمال کئے تھے ان کے مطابق اس کو ان کا بدلہ مل جائے اور اللہ تعالیٰ یقیناً حساب لینے میں جلدی کرنے والا ہے.اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جلدی عذاب دیتا ہے کیونکہ خود اس نے فرمایا ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حِسَابُہٗ سَرِیْعٌ جب حساب لینے لگتا ہے تو جلدی لے لیتا ہے.هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَ لِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ یہ (ذکر) لوگوں کے (نصیحت حاصل کرنے کے )لئے کافی ہے اور اس بات کے لئے (بھی ) کہ انہیں (آنے والے وَّاحِدٌ وَّ لِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِؒ۰۰۵۳ عذاب سے پورے طور پر ) ہوشیار کیا جائے اور اس لئے (بھی) کہ انہیں معلوم ہوجائے کہ وہ صرف ایک ہی معبود ہے اور اس (بات کے) لئے (بھی) کہ عقل والے (لوگ) نصیحت حاصل کریں حلّ لُغَات.اَلْبَلَاغُ الْکِفَایَۃُ.جو چیز کافی ہو.(اقرب) تفسیر.هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ.یہ لوگوں کے لئے پیام ہے یعنی اس پیام کے ذریعے لوگوں پر حجت پوری کی جاتی ہے.وَ لِيُنْذَرُوْا بِهٖ قرآن کریم ایک انذار ہے اس کے ذریعہ لوگوں کو ہوشیار کیا جاتا ہے جو غلطی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو وہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور جو سمجھ چکے ہیں انہیں وہ ہمیشہ استقلال سے صداقت پر قائم رکھنے کے لئے ہوشیار کرتا رہتا ہے تاکہ وہ روز بروز ہدایت میں بڑھتے رہیں.قرآن کریم بھی ایسی
Page 196
ایک کتاب ہے کہ جس کی آیات ایک ہی وقت میں دونوں کام کرتی ہیں.گمراہوں کو ہوشیار کرتی رہتی ہیں اور سمجھ والوں کو ترقی کی طرف توجہ دلاتی رہتی ہیں.اس آیت سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم ایک تخریبی تعلیم نہیں کہ اپنے سے پہلے مذاہب کو یا ان کے پیروؤں کو تباہ کرنے پر بس کرے.بلکہ وہ تخریبی ہونے کے علاوہ تعمیری بھی ہے.اگر وہ دنیا کو ان تعلیموں سے محروم کرتا ہے جن پر وہ پہلے چل رہی تھی تو وہ ان کی جگہ ایک ایسی تعلیم بھی پیش کرتا ہے جسے عقل تسلیم کرتی ہے اور فہم قبول کرتا ہے.اسی طرح اگر اس کے ذریعہ سے پہلا نظام حکومت تباہ کیا جائے گا تو ساتھ ہی ایک ایسا نظام قائم بھی کیا جائے گا جو پہلے سے بہتر ہوگا.
Page 197
سُوْرَۃُ الْـحِجْرِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ الحجر یہ سورۃمکی ہے وَھِیَ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ مِائَۃُ اٰیَۃٍ وَّسِتَّۃُ رَکُوْعَاتٍ اوربسم اللہ سمیت اس کی ایک سو آیات ہیں ـ.اورچھ رکوع ہیں یہ سورہ مکی ہے بحرِ محیط میں ہے.ھٰذِہِ السُّوْرَۃُ مَکِّیَّۃٌ بِلَاخلَافٍ.خدا کی قدرت ہے کہ اس سورۃ میں بہت سے مسائل ایسے ہیں.جن کی شان ہی اس سورۃ کے مکی ہونے سے بڑھتی ہے.اور اللہ تعالیٰ نے ایساتصرّف کیا کہ اسے مَکِّیَّةٌ بِلَاخِلَافٍ قرار دلوادیا.اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے.کہ اس میں بتایاگیاتھاکہ پہلے انبیاء بھی بغیر ظاہری سامانوں کے خدا تعالیٰ کے کلام کی مد د سے فتح پاتے رہے ہیں اب بھی اس طرح ہوگا.اب اس سورۃ میں بھی کلام الٰہی کی طاقت پر بحث کی گئی ہے.اوربتایاگیاہے کہ کلام الٰہی ایسی زبردست طاقت ہے.جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتااورجھوٹاکلام بناناآسان کام نہیں.خدا تعالیٰ پرافتراکرنے والابچ نہیں سکتا.پس یہ کلام سچا ہے اوراپناثبوت اپنے ساتھ لایا ہے.سورۃ کے مضامین کا خلاصہ اس سورۃ کے مضامین کاخلاصہ یہ ہے کہ یہ ایساکلام ہے کہ اپنامشابہ آپ ہے.یہاں تک کہ ایسے بہت سے مواقع پیش آتے ہیںاور آئیں گے.کہ اس کی خوبیوں کو دیکھ کر دشمن بھی دل میں حسرت کرتے ہیں.اورکریں گے کہ ایسا کلا م ان کے پاس کیوں نہ ہوا.مگر اپنی خود غرضیوں کی وجہ سے اس کی طرف قدم نہیں اٹھاسکتے.اورسمجھتے نہیں کہ اس قسم کی سستی کانتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان صداقت سے محروم رہ جاتا ہے اورعذاب میں مبتلاہوجاتا ہے.آخر جب ہم نے ایک کلام اتاراہے تویہ توہونہیں سکتا کہ وہ مٹ جائے.وہ قائم رہے گا اوررکھاجائے گا.پس جو اسے قبول کرنے میں سستی کریں گے وہ اپنانقصان خود کریں گے.پہلے نبیوں کے کلام سے بھی تمسخر ہوا.مگرلوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ خدا تعالیٰ پر افتراکرنامعمولی بات نہیں.خداخود اس امر کی حفاظت کرتا ہے کہ اس پر افترانہ کیاجائے.اور سچے کلام کو خاص امتیازعطافرماتا ہے.اس کی قبولیت کے سامان پیداکردیتا ہے اور جو اسے قبول کرتے ہیں.انہیں ادنیٰ حالت سے اٹھاکر کمال تک پہنچادیتا ہے.پس جس طرح پہلے انبیاء کے کلام ہی خزانے تھے جن کے ذریعہ سے دنیافتح ہوئی.اسی طرح اب بھی
Page 198
ہوگااگرمخالف پرواہ نہیں کرتے نہ کریں.وہ اس کی سزاپائیں گے.تُو اس خزانہ کو مومنوں میں تقسیم کر اورجواسےنہیں قبول کرتے اُنہیں سمجھاتا رہ.اور خدا سے دعائیں کر.کہ اسی ذریعہ سے تبلیغ کارستہ صاف ہوگا.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ( تعالیٰ) کا نام لے کر( شروع کرتا ہوں )جو بے حد کرم کرنے والا (اور)بار باررحم کرنے والا ہے الٓرٰ١۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ۰۰۲ الٓرٰ.یہ (ایک)کامل کتاب اور(اپنے مطالب کو خودہی)واضح کردینے والے قرآن کی آیات ہیں حلّ لُغَات.تِلْکَ ،آیَاتُ ،الْکِتَابِ کی تشریح کے لئے دیکھیں سورۃ یونس آیت نمبر ۲ نیز دیکھیں الرعد آیت نمبر ۲.مُبیْنٌ.مُبِیْنٌ اَبَانَ سے اسم فاعل ہے اوراَبَان لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے.یعنی کبھی اس کے معنے ظاہرکرنے کے ہوتے ہیں.اور کبھی ظاہرہونے کے.چنانچہ اقرب الموارد میں ہے.اَبَانَ الشَّیْءُ.اِتَّضَحَ.کوئی چیز ظاہر ہوگئی.(لازم)وَفُلَانٌ الشَّیْءَ.اَوْضَحَہُ کسی چیز کو واضح اور ظاہر کیا.(متعدی) سورۃ یوسف میں الْمُبِیْن کے معنے ظاہر کرنے والی کتاب کے تھے.اور اس جگہ خود ظاہرہونے کے ہیں.یعنی یہ بتانامقصود ہے کہ یہ کتاب اپنی آپ شاہد ہے.قراٰن کی تنوین تفخیم(بڑائی کے اظہار )کے لئے ہے.تفسیر.کیا الْكِتٰبِ اور قرآن میں کوئی فرق ہے؟ اس جگہ لوگوں نے بحث کی ہے کہ کیا اَلکِتٰب اور قُرْاٰنٌ مُّبِیْنٌ میں کوئی فرق ہے ؟کیونکہ یہاں پر درمیان میں وائو عاطفہ لائی گئی ہے.اور عطف بالعمو م مغائر اشیاء میں ہوتا ہے.دراصل انہیں یہ غلطی اس بات سے پیداہوئی کہ انہوں نے اَلْکِتٰب سے کاغذوں میںلکھی ہوئی کتاب سمجھ لیا ہے.الْكِتٰبِ اور قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍکے الفاظ کو مقابل پر رکھنے کی وجہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اَلکِتٰبِ اور قُرْاٰنٌ مُّبِیْنٌ کے الفاظ کو مقابل پر رکھ کر اس بات کو پیش کیا ہے.کہ قرآن مجید کی حفاظت تحریراوریاد دونوں ذریعوںسے کی جائے گی.یہ لکھابھی جائے گا.اور بکثرت پڑھابھی جائے گا.گویا.اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاالذِّکْرَ وَاِنَّالَہُ
Page 199
لَحَافِظُوْنَ (الحجر:۱۰) والے مضمون پرزور دیاگیا ہے اور اس جگہ معنوی طور پر قرآ ن مجید کی دوصفات کی طرف اشارہ کیاگیا ہے.الْكِتٰبِ میں قرآن مجید کے تحریر میں آنے کی طرف اشارہ ہے اور قُرْآنٍ میں پڑھے جانے کی طرف کِتٰبکے لفظ میں اس کے تحریر میں آنے کی طرف اشارہ ہے اور قُرْاٰنٍ کے لفظ میں اس کے بکثرت پڑھے جانے کی خبر دی گئی ہے.گویایہ دونام نہیں.بلکہ دوصفات ہیں.جیسا کہ کبھی محمدؐ کالفظ بطورصفت کے یعنی بہت تعریف کیاگیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.یہ دونوں صفات یکجائی طورپر صرف قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں.اس کے سوااور دنیا کی کسی الہامی کتاب میں یہ صفات جمع نہیں ہیں.انجیل اورتورات کثرت سے پڑھی جاتی ہیں.لیکن ان کو یاد کرنے والاکوئی نہیں.ویدوں کویادکرنے والاچھوڑ.ان کے معنے جاننے والے بھی شاذ ہیں.اس زمانہ میں سناہے پچیس کروڑ ہندوئوں میں سے معارف تو الگ رہے.صرف چار آدمی سارے ہندوستا ن میں ویدوں کاترجمہ سمجھ سکتے ہیں.یہی حال ژنداوستا کا ہے.صرف اور صرف قرآن کریم ہے جوکتابی صورت میں بھی پڑھاجاتا ہے اور حفظ بھی کیا جاتا ہے.اوردونوں صورتوں میں لاکھوں کروڑوں آدمی اس سے فائدہ اُٹھارہے ہیں.لفظ کتاب اور قرآن کو آگے پیچھے لانے کی وجہ اس جگہ ایک اور لطیفہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کے متعلق دوجگہ پر کتاب اور قرآن کالفظ اکٹھاآتاہے ایک جگہ قرآن کالفظ پہلے ہے اورکتاب کابعدمیں (النمل: ۲)اورایک جگہ کتاب کالفظ پہلے اورقرآن کالفظ بعد میں استعمال ہواہے.چنانچہ اس آیت میں کتاب کالفظ پہلے ہے اورقراٰن کابعد میں.میرے نزدیک یہ فرق درجہ کے تفاوت کو مدّنظر رکھ کر کیاگیاہے.سورہ حجر میں کتاب کی صفت سے زیادہ قرآن کی صفت کے اظہار پر زوردیاگیاہے.اس لئے کتاب کو پہلے اورقرآن کو بعد میں بیان کیاگیاہے.کیونکہ جب درجہ بیان کرناہوتوبڑی شے کو چھوٹی کے بعد بیا ن کیاجاتا ہے.اورسورہ نمل میںچونکہ قرآن کریم کی زبانی تلاوت سے زیادہ اس کی تحریرکے اثرکونمایاںکرناتھا.اس لئے اس میں قرآن کالفظ پہلے رکھا گیاہے اورکتاب کالفظ بعد میں رکھا گیا.کتاب اور قرآن کے لفظ کے ساتھ مختلف طور پر مبین کا لفظ لانے کی وجہ ایک اور امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت میں اَلْکِتَابِ کے ساتھ مُبِیْنٍ کالفظ نہیں ہے.مگر قرآن کے ساتھ مُبِیْنٍ کالفظ آیاہے اس کے برخلاف سورہ نمل کے پہلے رکوع میں اس آیت کے مضمون کو اُلٹ کربیان کیاہے.اورکہا ہے.
Page 200
تِلْکَ اٰیٰتُ الْقُرْاٰنِ وَکِتٰبٍ مُّبِیْنٍ یعنے قرآن کالفظ پہلے رکھ دیاگیاہے اور مبین کالفظ کتاب کے ساتھ لگادیا گیاہے.مبین کی صفت کا الگ الگ استعمال ہونا سجع کی غرض سے نہیں ممکن ہے بعض ناواقف لوگ جو اسرارِقرآنیہ سے واقف نہیں یہ خیال کریں کہ سجع کی خاطر ایساکردیاگیاہے.لیکن یہ درست نہیں کیونکہ اگر مبین سجع کی خاطر لگایاگیاتھا.تو قرآن کو کتاب سے پہلے کیوں کیاگیا.سورہ حجر والی ترتیب قائم رکھی جاتی او رکتاب کو پہلے اور قرآن کوبعد میں رکھاجاتا.پس ان الفاظ کی ترتیب کو بدل دینے سے صاف ظاہر ہے کہ مُبین کالفظ سجع کی غرض سے کتاب کے ساتھ نہیں لگایاگیا.بلکہ کسی اور حکمت کے ماتحت لگایاگیاہے مُبین کالفظ انہی دوسورتوں میںقرآن اورکتاب کے الفاظ کے ساتھ نہیں لگایاگیابلکہ اورسورتوں میں بھی ایساکیاگیاہے.مبین کی صفت کے کتاب کے ساتھ آنے کے بارہ مقامات قرآن کےساتھ ایک تو اس سورۃ میں.دوسرے سورۃ یٰس :۷۰ میںمبین کی صفت استعمال کی گئی ہے اور کتاب کے ساتھ ایک تو سورہ نمل کی مذکورہ بالاآیت میں اور دوسرے مندرجہ ذیل سورتوں میں یہ صفت بیان کی گئی ہے.(المائدہ:۱۶) (ھود:۷) (الانعام:۶۰)(یونس:۶۲)(سبا:۴)(النمل:۷۶)(الشعراء:۳)(القصص:۳)(یوسف:۲)(الزخرف:۳) (الدخان:۳)گویابارہ جگہ کتاب کی صفت مبین آئی ہے اور دوجگہ قرآن کی.پس سجع وغیرہ کاکوئی سوال نہیں.یہ تغیّریقیناًکسی حکمت کے ماتحت ہے.سورۃ نمل میں کتاب کے ساتھ مبین کی صفات آنے کی وجہ قرآن اورکتاب کے الفاظ اس قسم کے موقع پر دوہی جگہ جمع ہوئے ہیں.ان میں سے ایک میں تو کتاب کو پہلے رکھا گیا ہے اور قرآن کو بعد میں اورقرآن کی صفت مبین بیان ہوئی ہے اوردوسری جگہ قرآن کو پہلے بیان کیاہے اورکتاب کو بعد میں اورکتاب کے ساتھ مبین کالفظ بیان ہواہے اوراصل مواقع یہی ہیں جوغورطلب ہیں.کہ کیوں ایک جگہ قرآن کے ساتھ اور دوسری جگہ کتاب کے ساتھ مبین کالفظ استعمال کیاگیاہے.سورئہ حجر اور نمل کے مضامین میں فرق اس کا جواب یہ ہے کہ سورئہ حجر اور سورہ نمل کے مضامین میں ایک فرق ہے سورئہ حجر میں ان انبیاء کا ذکر ہے.اور ان کے حالات زندگی کو بطور تمثیل پیش کیاگیاہے جن میں کتابت کارواج کم تھااور علوم کو زبانی یاد رکھاجاتاتھا.یعنے حضرت آدم ؑ حضرت ابراہیم ؑ.ان کے رشتہ دار.حضر ت لوط ؑ اور اصحاب ایکہ یعنے بَن والے لوگ اور قوم صالح ؑ.
Page 201
قرآن مبین کہنے سے وہ قومیں مخاطب ہیں جن میں تحریر کا رواج کم تھا حضرت آدم ؑ کا زمانہ ابتدائی تھا.اورغالباًتحریرکافن ابھی شروع بھی نہ ہواتھا.حضرت ابراہیم ؑاور حضرت لوط ؑ عربی قبائل میں سے تھے.اور عراق ان کا مولد تھاان میں بھی تحریرکاروا ج کم تھا.اصحاب الایکہ بھی عرب کا قبیلہ تھے اور قوم صالح ؑبھی اور ان سب میں تحریر کا رواج کم تھا پس ان مثالوں سے ثابت ہے.کہ سورئہ حجر میں زیادہ ترخطاب ان اقوام سے ہے.جن میں تحریرکارواج کم تھا.اورجنھوں نے حفظ کے ذریعہ سے قرآنی علوم سے زیادہ فائدہ اٹھاناتھا.پس اس سورۃ میںقرآن کےساتھ مبین کالفظ رکھا یہ بتانے کے لئے کہ ان اقوام میں اس کلام کی صفت قرآن لوگوں کوزیادہ فائدہ پہنچائے گی.لیکن کتاب کی صفت بھی ساتھ بیان کی تاکہ مکمل حفاظت کااظہار ہو.اس کے بالمقابل سورئہ نمل میں کتاب کے ساتھ مبین کالفظ لگایاگیاہے.کیونکہ اس سورۃ میں حضرت موسیٰ علیہ لسلام اور حضرت دائود ؑکے واقعات پر زور دیاگیاہے جوبنی اسرائیل میں سے تھے.جن میں لکھنے کارواج بہت تھااورزبانی یاد رکھنے کارواج کم تھا(The Illustrated Bible Dictionary underword WRITING)اوران انبیاء کے اتباع نے محمد رسول اللہ صلعم پر نازل ہونے والے کلام کی صفت کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھاناتھابہ نسبت صفت قرآن کے.اس لئے اس کی مناسبت سے سورئہ نمل میں قرآن کے لفظ پر زورکم دیااورکتاب پر زیادہ.غرض سورئہ حجرمیں تویہ بتایاہے کہ قرآن کریم گو لکھابھی گیاہے مگربعض اقوام جوحافظہ سے زیادہ کام لینے والی ہیں.اس کویادکرکے اورسن کر زیادہ فائدہ اٹھائیں گی.اوراس سورۃ میں وہی ہماری بڑی مخاطب ہیں او رسورۃ نمل میں یہ بتایاگیاہے کہ قرآن کریم گوحفظ بھی کیاجائے گالیکن لکھا بھی جائے گا.اوربعض قومیں جو تحریرسے زیادہ فائدہ اٹھانے والی ہیں.وہ اسے کتاب سے پڑھ کرزیادہ فائدہ اٹھائیں گی اور ا س سورۃ میں وہی ہماری بڑی مخاطب ہیں.قرآن مجید سے تمام قومیں فائدہ اٹھائیں گی حافظہ سے کام لینے والی بھی اور تحریر سے بھی خلاصہ یہ کہ قرآن کریم قرآن ہونے کے لحاظ سے بھی مبین ہے اور کتاب ہونے کے لحاظ سے بھی.او رچونکہ وہ سب دنیا کی طرف ہے اس سے وہ قومیں بھی فائدہ اٹھائیں گی جوحافظہ سے زیادہ کام لیتی ہیں.ان کے لئے وہ قرآن مبین ہوگااوروہ قومیں بھی فائدہ اٹھائیں گی جوتحریرسے وابستہ ہیں اور ان کے لئے وہ کتاب مبین ہوگا.کتاب کے ساتھ مبین کی صفت کا کثرت استعمال جیساکہ میں نے بتایاہے.قرآن مبین کالفظ دو دفعہ استعمال ہوا ہے.اورکتاب مبین کا بارہ دفعہ.اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن کریم کاکتاب ہونے کے لحاظ سےحلقہ وسیع ہوگا اور اکثر لوگ اس کے کتاب ہونے کے لحاظ سے فائدہ اٹھائیں گے.یعنی
Page 202
کثیرالتعداد اقوام میں وہ پھیل جائے گا.جوکتابت سے علوم کو محفوظ کرتی ہیںمیرے نزدیک قرآن کریم میں دس جگہ کتاب کے ساتھ مبین کے لفظ کااستعمال کرنااوردوجگہ قرآن کے ساتھ مبین کےلفظ کااستعمال اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ کتاب سے فائدہ اٹھانے والے زیادہ ہوتے ہیںبہ نسبت حفظ سے فائدہ اٹھانے والوں کے.اورمسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تعلیم کے رواج کو زیادہ کریں.تاکہ مسلمان قرآنی فوائد سے محروم نہ رہ جائیں.تحریر اور حفظ دونوں مل کر پوری حفاظت کر سکتے ہیں.اس سورۃ میں تعلیم اسلام کی حفاظت کا ذکر ہے اس سورۃ میں تعلیم اسلام کی حفاظت کا ذکر ہے اس لئے اس کی دونوں صفات یعنے کتاب اورقرآن بیان کی گئی ہیں.کسی مضمون کی حفاظت کبھی مکمل طور پرنہیں ہوسکتی.جب تک وہ تحریر اور حفظ دونوں ذریعہ سے محفوظ نہ کیاجائے.انسانی حافظہ بھی غلطی کرجاتاہے اورکاتب بھی بھول چوک جاتا ہے.لیکن یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی غلطی کو نکال دیتے ہیں اوران دوسامانوں کے جمع ہونے کے بعد غلطی کاامکان باقی نہیں رہ سکتا.قرآن کریم کویہ دونوںحفاظتیں حاصل ہیں.یعنے وہ کتاب بھی ہے.رسول کریم صلعم کی زندگی سے ہی اس کے الفاظ تحریر کرکے ضبط میں لائے جاتے رہے ہیں اور وہ قرآن بھی ہے.یعنے نزول کے وقت سے آج تک سینکڑوں ہزاروں لوگ اسے حفظ کرتے اور اس کی تلاوت کرتے چلے آئے ہیں.رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ۰۰۳ جن لوگوں نے(اس کا)انکارکیاہے.وہ بسا اوقات آرزوکیاکرتے ہیں.کہ کاش وہ (بھی اس کی)فرمانبرداری اختیارکرنے والے ہوتے.حل لغات.رُبَمَا.رُبَ اور مَا کامرکب ہے رُبَ کبھی رُبَّ یعنی ب کی تشدید سے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے متعلق یہ اختلاف ہےکہ یہ حرف ہے یااسم.بصریوں کے نزدیک اورنیز اکثر ائمہ لغت و نحو کے نزدیک یہ حرف ہے لیکن کوفی نحوی اسے اسم بتاتے ہیں.بصری کہتے ہیں کہ رُبَ کے بعد ما کا لفظ اس لئے لایاگیا ہے کہ یہ حرف تھاکیونکہ حرف جرّ فعل پرنہیں آسکتا.رُبَ کے معنوں کے متعلق اختلاف رُبَ کے معنوں کے متعلق بھی اختلاف ہے.اکثر لوگوں نے اسے
Page 203
تقلیل کے لئے قرار دیاہے یعنی جس واقعہ پر رُبَما داخل ہوتا ہے.وہ کبھی کبھی او رشاذو نادرکے طورپرہوتاہے ابوعبداللہ رازی نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہ تقلیل کے لئے آتا ہے.زمخشری کابھی یہی خیال ہے مگرسیبویہ کی طرف ایک روایت منسوب ہے.کہ یہ تکثیر کے معنوںمیں بھی آتاہے.زجاج کابھی یہی قول ہے.بعض علماء کا خیال ہے کہ رُبَمَا نہ تقلیل کے لئے آتا ہے نہ تکثیرکے لئے.بلکہ سیاق وسباق کے ماتحت تکثیر یاتقلیل کے معنی دیتا ہے جب تقلیل کاموقع ہوتوتقلیل کے معنے دیتا ہے اوراگرتکثیرکاموقع ہو.توتکثیر کے.اس کے ذاتی معنے کوئی نہیں.یہ صرف اس بات پردلالت کرتا ہے کہ مابعد کاواقعہ ضرور ہواہے ( لسان العرب.والبحر المحیط و الکشاف ، و الرازی) اس آیت میں رُبَمَاکے معنے تکثیرکے ہی لئے جاتے ہیں جن لوگوں نے ربماکوتقلیل کے لئے قراردیا ہے انہوں نے بھی اس جگہ تاویل کر کے تکثیرہی کے معنی لئے ہیں.( لسان العرب) رُبَمَا کے متعلق ایک اور بحث اسی طرح رُبَ کے متعلق ایک اوربحث ہے.اکثرلوگوں کی رائے ہے کہ رُبَما ہمیشہ ماضی کے معنوں کے بیان کرنے کے لئے آتا ہے خواہ اس کے بعد فعل مضارع ہی کیوں نہ ہو.ان لوگوں نے رُبَمَایَوَدُّ کے معنے رُبَماوَدّ کئے ہیں.اورپھرکہا ہے کہ رُبَمَایَوَدُّ فعل جو قاعد ہ کے روسے ماضی کے معنے دیتا ہے.رُبَمَا کا لفظ مستقبل کے معنے میںبھی آتا ہے اس جگہ مستقبل کے لئے اس لئے استعمال کیاگیا ہے.تاکہ یقین کے معنوں پر دلالت کرے لیکن عربی زبان کاتفحّص کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رُبَ کالفظ مستقبل کے معنے میں بھی آتا ہے.ہندہ زوجہ ابوسفیان کہتی ہے ؎ یَا رُبَّ قَائِلَۃٍ غَدًا یَالَھْفَ اُمِّ مُعَاوِیَۃَ (البحر المحیط زیر آیت ھذا) اس میں یقیناً مستقبل کے معنے ہیں.جیساکہ غَدًا کالفظ دلالت کرتا ہے.پھر اسی طرح ایک شاعر سلیم القشیری کاشعر ہے ؎ وَمُعْتَصِمٍ بِالْجُبْنِ مِنْ خَشْیَۃِ الرَّدَی سیَرْدَی وَغَازٍ مُشْفِقٍ سَیَؤُوْبُ (البحر المحیط زیر آیت ھذا)
Page 204
یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے بزدلی کی پناہ لینے والا ہلاک ہوجائے گا.لیکن جو ڈر کو دور پھینک دیتا ہے اور جنگ کے لئے نکل کھڑاہوتا ہے وہ زندہ سلامت واپس آئے گا.اس جگہ پر رُبَ محذوف ہے.جیسا کہ مُعْتَصِمٍ کی جَرّ سے ظاہر ہے اور شعر کے معنے یقیناً مضارع پردلالت کرتے ہیں.کیونکہ سَیَـرْدٰی اور سَیَئُوْبُ مضارع کے صیغے ہیں.غرض رُبَ مستقبل کے معنوں میں بھی آتا ہے اورتکثیر کے لئے بھی.جیسا کہ سیبویہ اورزجاج کے قول سے اوپر ذکرہوچکا ہے.اَسْلَمَ اَسْلَمَ سے اسم فاعل مُسْلِمٌ آتاہے.اورمُسْلِمُوْنَ اس کی جمع ہے اَسْلَمَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں تَدَیَّنَ بِالْاِسْلَامِ مذہب اسلام قبول کرلیا.اوراَسْلَمَ اَمْرَہٗ اِلَی اللہ کے معنے ہیں سَلَّمَہٗ کہ اپنے معاملہ کو اللہ کے سپرد کردیا (اقرب) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ کے معنے ہوںگے.بسا اوقات منکریہ آرزوکرتے ہیں یاکریںگے کہ وہ اسلام کو قبول کرلیتے (۲)وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپردکردیتے.تفسیر.کفار کی خواہش کے متعلق مفسرین کی بحث کفارکی اس خواہش کے متعلق مفسرین نے بحث کی ہے کہ کب انہوں نے خواہش کی کہ وہ مسلمان ہوں؟بعض نے مجبورہوکرکہاکہ وہ اس وقت یہ خواہش کریں گے جب مسلمانوں کی فتح ہوگی.بعض نے قیامت پرچسپاں کیا ہے کہ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے.اور بعض نے اس سے ترقیات اسلامی مراد لی ہیں.یعنی جب بھی ترقی ہوگی وہ یہ خواہش کریں گے.(تفسیر فتح البیان تفسیر سورۃ حجر زیر آیت ھذا) آنحضرت ﷺ کی غیر معمولی ترقی سے کفار مسلمان ہونے کی خواہش کرتے ہیں یہ معنے بھی درست ہیں.ان پر کوئی اعتراض نہیں.کیونکہ جب دشمنی بلاوجہ ہوتی ہے جیسا کہ کفار عرب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی تودشمن کی ترقی پر انسان کو اکثر یہ خیال آجاتاہے کہ میں اس کی دشمنی نہ کرتا.تواچھاتھا.آج فائدہ ہی اٹھالیتا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی محض حسد کی وجہ سے تھی.اورآپؐ کی غیر معمولی ترقیات سے وہ حسد کے مواقع ہی جاتے رہے.اس لئے ان کو بارہاخیال آتاہوگاکہ کاش ہم مسلمان ہوتے.اسی طرح جب وہ بدرکے مقام پر قتل ہورہے تھے توان کادل یہی چاہتاہوگاکہ کاش ہم مسلمان ہوتے.غرض اسلام کی فتوحات دشمنوں کے دلوں میں یہ حسرتیں ضرورپیداکرتی ہوںگی.کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے.منافقوں کاقول توقرآن مجید میں صریح طورپربیان ہواہے کافروں کی بھی یہی حالت ہوتی ہوگی.یہ ایک طبعی بات ہے اس سے انکار نہیں ہوسکتا.
Page 205
اس آیت کے ایک اور معنے میرے نزدیک ان کے علاوہ آیت کے ایک اورمعنے بھی ہیں.مفسّرین عام طور پر ظاہری لطافت.فصاحت و بلاغت اورمعجزات پر بحث کرتے ہیں.اورقرآن مجید کی تعلیمی خوبیوں پر بہت کم بحث کرتے ہیں.میرے خیال میں سب سے بڑی چیز جس کے لئے قرآن کریم آیا ہے.وہ اس کی کامل اور دلکش تعلیم ہے اور اسی کی طرف تِلْکَ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ میں اشار ہ کیا ہے.اورآیت رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا میں انہی تعلیمی خوبیوں پر رشک کا ذکرکیاہے یعنی فرماتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی خوبیوں کو دیکھ کر بارہاکافر کہہ اٹھتے ہیں اورکہہ اٹھیں گے.کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اوریہ ہمیشہ ہوتارہاہے اورہوتارہے گا.حضرت عمر ؓسے ایک یہودی نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے.اگر وہ ہماری کتاب میں اترتی توہم اس دن عید مناتے.حضرت عمرؓ نے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے.اس نے جواب دیا.اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ.الآیہ.آپ نے فرمایا.وہ دن تو ہمارے لئے دوعیدوں کادن تھا.یعنی جمعہ کا دن اورعرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی.(بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ).ایک یہودی کا اسلامی شریعت کے اعلیٰ ہونے کا اعتراف ایسا ہی ایک اور یہودی نے کہاکہ آپ کی شریعت میں ایک بات دیکھ کر حیرت ہوجاتی ہے کہ انسانی زندگی کاکوئی حصہ نہیں جس پر اس شریعت نے روشنی نہ ڈالی ہو(الترمذی ابواب الطہارۃ ،باب الاستنجاء بالحجارۃ).یہ خواہشات ہیں جو ہزاروں کے دلوں میں پیداہوئی ہوںگی.مگر اظہار ان کادوایک کے منہ سے ہوا.اورقرآن مجید نے بھی فرمایا ہے یَوَدُّ ُّ(ان کے دل چاہتے ہیں ) یقول نہیں فرمایا(کہ وہ منہ سے بھی اظہارکرتے ہیں).اس زمانہ میں اسلامی تعلیم کے قابل رشک مسائل اس زمانہ میں بھی طلاق کامسئلہ.شراب کامسئلہ.ورثہ کامسئلہ.اورایسے ہی اور بہت سے مسائل ہیں کہ جن پر دنیارشک کررہی ہے.جب ایک یورپین کے دل میں خیال آتاہے کہ ہمارے ہاں بھی طلاق کاقانون بنناچاہیے.تودوسرے معنوں میں وہ یہی کہتا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا.ایسا ہی جب ایک امریکن کے دل میں یہ تحریک پیداہوتی ہے کہ شراب بندہونی چاہیے.تووہ گویا رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ کی تصدیق کرتا ہے.ایک ہندو کا اسلامی ازدواجی قانون پر رشک ابھی کچھ عرصہ ہوا ہندوستان کی لیجسلیٹو اسمبلی کے ایک ہندوممبر نے صغرسنی کی شادی کے متعلق مسودہ قانون پیش کیاتھا.اس نے دورانِ تقریر میں کہا.میں بڑی حسرت سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح اسلام نے شادی کاقانون بناکر مسلم قوم کو محفوظ کردیاہے.ویساقانون
Page 206
ہمارے ہاں کوئی نہیں.آیت میں بھی رُبَمَا کالفظ رکھا گیا ہے.جوکئی دفعہ پردلالت کرتاہے.یعنی ان لوگوں کو بحیثیت مجموعی اسلام لانے کاخیال پیدانہ ہوگا.بلکہ الگ الگ مسائل پر ان کے دل میںیہ خواہش پیداہوگی کہ کاش یہ مسئلہ بھی ہمارے پاس ہوتا.یہ بھی ہوتا.مسلم کے معنے سپرد کردینے والےکے مُسْلم کے معنے سپرد کردینے والے کے بھی ہیں.جیسے فرمایا اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (البقرة :۱۳۲) میں نے اپناسب کچھ اللہ کے سپردکردیا.پس اس آیت کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں.کہ جب کفار اپنی دنیوی تدابیرکو بیکار جاتے دیکھتے ہیں اورمحمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )کوجوصرف اللہ تعالیٰ پرتوکل کئے بیٹھے ہیں.کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں.توان کاغرورایک وقت کے لئے کمزورپڑجاتاہے اوران کے دل میں خواہش پیداہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے اوراپنے معاملات اس کے سپردکردیتے.توان ذلّتوں اورشکستوںکامنہ نہ دیکھتے.مسلم کے معنی امن دینے والے کے ہیں مسلم کے معنے امن دینے والے کے بھی ہوتے ہیں.ان معنوں کو مدنظررکھتے ہوئے آیت کے یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں.کہ مسلمانوں کی ترقیات کو دیکھ کر کبھی کبھی کافروں کے دل میں یہ خیال آتاہے کہ کاش ہم اس قوم سے لڑائی نہ چھیڑتے اورصلح رکھتے اوریہ روزِ بدنہ دیکھتے.جو اَب دیکھنانصیب ہوا.ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ توان کو(اپنے حال پر)چھوڑدے کہ وہ (بیٹھے کھانے )کھاتے رہیں.اوروقتی سامانوں سے نفع اٹھاتے رہیں يَعْلَمُوْنَ۰۰۴ اور(انکی جھوٹی) امیدیں انہیں غافل کرتی رہیں.کیونکہ وہ جلد(ہی حقیقت )معلوم کرلیںگے.حلّ لُغَات.اَلْاَمَلُ وَالْاَمْلُ اس کی جمع آمَالٌ ہے.اوراَلْاَمْلُ کے معنے ہیں.الرَّجَاءُ.امید.تَاَمَّلْتُ الشَّیْئَ اَیْ نَظَرْتُ اِلَیْہِ مُسْتَثْبِتًالَہٗ.تَاَمَّلْتُ الشَّیءَ کے معنے ہیں.اسے غورسے دیکھا.ٹکٹکی لگا کر دیکھا (اقرب)
Page 207
تفسیر.اس آیت میں یہ بتلایاہے کہ یہ لوگ مختلف مسائل میں اسلام کی برتری توتسلیم کرتے ہیں.اورکریں گے.مگرپھر بھی اسلام کی طرف قدم اٹھانانصیب نہ ہوگا.یورپ کے لوگ اسلامی مسائل کی برتری کومانتے ہیں مگراسلام لانے کے لئے طیار نہیں.کیونکہ سوسائٹی کاسوال ہے.فرمایاوہ اپنے اکل و شرب کی وجہ سے اپنی تجارتوںاورصنعتوں کی وجہ سے اوراپنی بعید آرزوئوں کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے.اس میں گویاپہلی آیت کے مفہوم پر جوسوال پیدا ہوتاتھا.اس کا جواب دیاگیاہے.یعنی جب وہ لوگ خواہش کرتے ہیںاورکریں گے ’کاش وہ مسلمان ہوتے‘ تووہ مسلمان ہوتے کیوں نہیں ؟فرمایا ان کی عیاشی دولت کی حرص اورطولِ امل ان کے راستہ میں روک بن رہے ہیں.صداقت قبول کرنے کے لئے کھانے پینے میں سادگی ضروری ہے اس آیت سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ صداقت کو قبول کرنے کے لئے کھانے پینے میں سادگی دنیا کی حرص سے اجتناب اورطول امل سے بچنا ضروری امور ہیں جوشخص صداقت کاجویاہواس کے لئے ان سے بچنا ضروری ہے اگر کوئی ان تین باتوں سے نہیں بچتاتواس کاصداقت کی جستجو کرنافضول امر ہے.اگرحق اس پر کھل بھی جائے گا تب بھی وہ اس کے قبول کرنے سے محروم رہے گایہ اشارہ بھی اس آیت میں ہے کہ کفار لوگوں پر رعب جمانے کے لئے اپنے دسترخوان کوخوب وسیع کرتے دولت کماتے اورمحمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح پانے کے لئے دوردورکی تدابیراختیارکرتے تھے جبکہ محمد رسول اللہ صلعم ان سب باتوں سے خالی تھے مگرباوجود اس کے فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیتیں گےاورکفار کے دلوں میں آ پؐ کی کامیابی دیکھ کر حسرت پیداہوگی.لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ کہناکفّار کاعارضی جذبہ ہے اس آیت سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَکفّار کاعارضی جذبہ ہے ورنہ اصل میں وہ کھانے پینے اوردولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں اورعارضی جذبات انسان کو نفع نہیں دیتےبلکہ مستقل جذبات فائدہ دیتے ہیں مسلمانوں کامستقل جذبہ مسلم ہونے کاہے عارضی طورپر وہ کھاتے پیتے دولت کماتے اوربعض تدابیر بھی آئندہ کے لئے کرلیتے ہیں پس باوجود ان کاموں کے وہ ہدایت پارہے ہیں جبکہ کافرہدایت نہیں پاتے.
Page 208
وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ۰۰۵ اورہم نے کبھی کسی بستی کوبغیراس کے کہ اس کے متعلق (پہلے سے )ایک معلوم فیصلہ ہوچکاہوہلاک نہیں کیا.حلّ لُغَات.اَلْقَرْیَۃ.کے معنی بستی کے ہیں.نیز قریہ بول کر اہل قریہ بھی مراد لیتے ہیں.تفصیل کے لئے دیکھو حل لغات یوسف آیت نمبر ۸۳ نیز یونس آیت نمبر ۹۹.القریۃ.اَلْمِصْرُ اَلْجَامِعُ بڑا شہر.کُلُّ مَکَانٍ اِتَّصَلَتْ بِہِ الْاَبْنِیَۃُ وَاتُّخِذَ قَرَارًا ہر آبادی کی جگہ خواہ شہر ہو یا گاؤں.جَمْعُ النَّاسِ.لوگوں کی جماعت.(اقرب) اَلْقَرْیۃُ اِسْمٌ لِلْمَوْضَعِ الَّذِیْ یَجْتَمِعُ فِیْہِ النَّاسِ.قَریة اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں.وَلِلنَّاسِ جَمِیْعًا اور جمع شدہ لوگوں کو بھی قریة کہتے ہیں.وَیُسْتَعْمَلُ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْہُمَا.اور قریہ ان ہر دو معنے میں استعمال ہوتا ہے.قَالَ تَعَالٰی وَاسْأْلِ الْقَرْیَۃَ قَالَ کَثِیْرٌ مِّنَ الْمُفَسّرِیْنَ مَعْنَاہُ اَھْلَ الْقَرْیَۃِ مذکورہ بالا آیت میں وَاسْأَلِ الْقَرْیَۃَ کے معنے اکثر مفسرین نے اَھْلُ قَرْیَۃٍ ’’یعنی بستی کے رہنے والے‘‘ کئے ہیں.وَقَالَ بَعْضُھُمْ بَلِ الْقَرْیَۃُ ھٰھُنَا الْقَوْمُ اَنْفُسُھُمْ اور بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ قریہ سے مراد خود لوگ ہی ہیں اہل قریہ نہیں.(مفردات) وَلَھَا میں وائو حالیہ ہے وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ.وَ لَهَا میں واؤ حالیہ ہے.قاضی منذر نے لکھاہے کہ اس کامطلب یہ ہوتاہے کہ اس کے بعد کامذکور اس کے قبل کے مذکور سے زمانہ میں پہلے واقعہ ہوچکاہے.جیساکہ آتاہے حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا (الزمر:۷۴)(البحر المحیط تفسیر سورة الحجر زیر آیت ھٰذا) تفسیر.قریة سے مراد نبی کے تمام مخاطب ہوتے ہیں یادرکھناچاہیے کہ قریہ سے مراد گائوں یابستی نہیں بلکہ وہ قوم مراد ہے جن کی طرف نبی آتاہے.یہ قرآن مجید کامحاورہ ہے کہ وہ قریہ کالفظ بول کر مراد نبی کے تمام مخاطب لیتا ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مخاطب نبی کے گائوں یاشہر والے ہی ہوتے ہیں.دوسروں کو ان کے تابع کردیاجاتاہے.نبی کی بستی کو اُمّ القریٰ قراردیاجاتاہے جب ماں مرجائے توبچے آپ ہی بے غذامرجاتے ہیں.اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ سے مراد اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ میں مراد وہی قریہ ہے جس میں نبی آتاہے دوسری بستیوںکا ذکر اس لئے چھوڑ دیا کہ وہ اس بستی کے تابع ہیںاس کامزیدثبوت اگلی آیت میں من امۃ کے لفظ
Page 209
سے مل جاتا ہے.ایک اعتراض کا جواب یاد رکھنا چاہیے کہ جولوگ یہ کہتے ہیں فلاں گائوں ہلاک ہوگیا فلاں شہر میں بیماری پڑ ی مگر اس میں کوئی نبی نہ تھاان کایہ اعتراض غلط ہے اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیاگیاہے نبی کی بعثت کے بعد اس کے مخاطبین کی سب بستیاں عذاب کی مستحق ہوجاتی ہیں اوربتایاگیاہے کہ جب نبی مبعوث ہوتو اس کے مخاطبین کی سب بستیاں اس کی بستی کے تابع سمجھی جاتی ہیں اوراس بستی میں نبی کی بعثت کے بعد سب بستیاں عذاب کی مستحق ہوجاتی ہیں اگروہ ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتووہ ساری قوم انکار کے باعث مستحقِ عذاب ہوتی ہے خواہ ان کی بستیوں میں سے و ہ نبی گزرابھی نہ ہواور اگر وہ سب دنیا کی طرف ہوتو سب دنیامستحق عذاب ہوجاتی ہے نیز اس آیت سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ کسی بستی پر عذاب آنا اس بات کی علامت نہیں کہ ضرورکوئی نبی آیا ہوبلکہ اسی قدر وسیع عذاب جس قدر وسیع نبی کاحلقہ ہونبوت کی دلیل ہوتاہے اگرایک قوم کی طرف نبی ہوتوقومی عذاب نبی کی علامت ہےاور اگر ایسے نبی کا زمانہ ہوجو سب دنیا کی طرف مبعوث ہواہوتوپھر عالمگیر عذاب ہی اس کی علامت ہے یہ کہنا حماقت ہے کہ اگرعذاب بغیر نبی کے نہیں ہوتاتوفلاں گائوں کیوں ہلاک ہواتھااس وقت کون نبی آیاتھایہ عذاب جو نبوت کی علامت ہوتاہے اس وسیع حلقہ کااحاطہ کرتاہے جونبی کامخاطب ہوتاہے بنی اسرائیل کے نبیوں کے لئے کسی ایک گائوں کاعذاب نہیںبنی اسرائیل کی قوم کاعذاب علامت تھااور محمد رسول اللہ صلعم کے لئے کسی قوم کاعذاب نہیں بلکہ دنیابھر کی تباہیاں علامت تھیں.آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں عرب پر خصوصاً عذاب آیا جیساکہ تاریخ شاہد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب پرخصوصاً عذاب آیامگرساری دنیاپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قلیل عرصہ میں تباہی نازل کی.(بخاری کتاب التفسیر سورة الدخان باب یغشی الناس ھذا عذاب الیم) كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌسے مراد كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌسے مراد وہ مدت ہے جو انبیاء کے ذریعہ سے بتادی جاتی ہے اوراس جگہ قریة سے مراد وہی لوگ ہیںجن کو نبیوں کی مخالفت کی وجہ سے عذاب ملتا ہے.ایسے لوگوں پر عذاب ہمیشہ کھُلی پیشگوئیوں کے بعد آتاہے.
Page 210
مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ۠۰۰۶ کوئی قوم بھی اپنی (ہلاکت کی ) میعاد سے بھاگ (کر بچ) نہیں سکتی.اور نہ ہی پیچھے رہ( کر اس سے بچ) سکتی ہے حلّ لُغَات.الاجل کی تشریح کے لئے دیکھوسورۃ رعدآیت نمبر۳۹.اَلْاُمَّۃُ.اَلْجَمَاعَۃُ.امت کے معنے ہیں جماعت.الْجِیْلُ مِنْ کُلِّ حیٍّ.ہرقبیلے کے ہمعصرلوگ.(اقرب) تفسیر.مَاتَسْبِقُ اور مَایَسْتَأْخِرُوْنَ کامفہوم بالعموم لوگوں نے مبہم سابیان کیاہے.میرے نزدیک ماتسبق کامطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ عذاب سے کوئی قوم جس کے متعلق عذاب کی خبر ہودامن چھڑاکرنکل جائے یعنے عذاب تووقت پر آجائے لیکن نقصان نہ پہنچائے اوروہ ہلاکت سے بچ جائے اورنہ یہ ہوسکتا ہے کہ قوم عذاب سے پیچھے رہ جائے یعنے عذاب ٹلتاہی چلاجائے اورملتوی ہوتاجائے گویاڈھیل بے شک ایک ضروری شے ہے اورنبی کے مخالفوں کو ضرور ملتی ہے تاجو ہدایت پانے کے قابل ہیں ہدایت پا جائیں مگریہ نہیں ہوتاکہ ڈھیل ہی ملتی جائے اورعذاب نبی یااس کے اتباع کے زمانہ میں ظاہر ہی نہ ہو.اس آیت میں کفار کو ایک تنبیہ اس آیت میں کفار کو اس سے متنبہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں کیونکہ وہ دوہی طرح محفوظ رہ سکتے ہیں (۱)یاتوعذاب آئے مگر ان کو ہلاک نہ کرے.(۲) یاپھرعذاب ٹلتاہی جائے.فرمایایہ دونوں باتیں نہ ہوںگی.پس ڈھیل پر دلیر نہ ہوں.وَ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌؕ۰۰۷ اور انہوں نے (بڑے زور سے ) کہا ہے (کہ )اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے حلّ لُغَات.الذّکر.الذِّکْرُالتَّلَفُّظُ بِالشَّیْءِ وَاِحْضَارُہُ فِی الذِّھْنِ بِحَیْثُ لَایَغِیْبُ عَنْہُ.ذکر کے معنی ہیں.کسی چیزکامنہ سے ذکرکرنااورایسے طور پریاد اورمستحضر فی الذھن کرنا.کہ وہ بھول نہ جائے.اَلصِّیْتُ.شہرت وَمِنْہُ لَہٗ ذِکْرٌفِی النَّاسِ.اورانہی معنوں میں لَہٗ ذِکْرٌ فِی النَّاسِ کافقرہ بولتے ہیں.کہ فلاں شخص کولوگوں میں شہرت حاصل ہے.اَلثَّنَاءُ.تعریف.اَلشَّرَفُ.شرف.وَفِی الْقُرْاٰنِ اِنَّہٗ لَذِکْـرٌ لَّکَ وَلِقَوْمِکَ.اورقرآن مجید میں اِنَّہٗ لَذِکْرٌ لَّکَ وَلِقَوْمِک انہی معنوں میں استعمال ہواہے.کہ قرآن مجید کانزول تیرے
Page 211
اورتیری قوم کے لئے شرف کاموجب ہے.وَالصَّلَاۃُ لِلہِ تَعَالیٰ والدُّعَاءُ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا.چنانچہ انہی معنوں میں یہ فقرہ استعمال ہوتاہے.اِذَاحَزَبَہٗ اَمْرٌفَزِعَ اِلَی الذِّکْرِکہ جب مصیبت کاسامناہوا.تواس نے دعاکی طرف جلدی کی.اَلْکِتَابُ فِیْہِ تَفْصِیْلُ الدِّیْنِ وَوَضْعُ الْمِلَلِ ایسی کتاب جس میں دین کی تفصیل ہو.اور شریعت کے اصول بیان کئے گئے ہوں.مِنَ الرِّجَالِ.اَلْقَوِیُّ الشُّجَاعُ الْاَبِیُّ.ایسابہادرشخص جوکسی کارعب برداشت نہ کرے.مِنَ الْمَطْرِ.اَلْوَابِلُ الشَّدِیْدُ.سخت موسلا دھار بارش.مِنْ القَوْلِ.اَلصُّلْبُ الْمَتِیْنُ.پکی بات.(اقرب) المجنون.اَلْمَجْنُوْنُ جُنَّ الرَّجُلُ.جَنًّا وجُنُوْناً زالَ عَقْلُہٗ وَقِیْلَ فَسَدَ.عقل جاتی رہی یاعقل میں فتور آگیا.الجُنُونُ مَصْدَرُجَنَّ جنون.جَنَّ َّ کامصدر ہے جس کے معنے ہیں چھپانا.زَوَالُ الْعَقْلِ.عقل کاجاتے رہنا.وَقِیْلَ فَسَادَہٗ عقل میں خرابی کاپیداہونا.اَلْمَجْنُوْنُ مَنْ زَالَ عَقْلُہ أَوْ فَسَدَ اورمجنون ایسے شخص کوکہتے ہیں جس کی عقل جاتی رہے یاعقل میں فتورپیداہوجائے.(اقرب) القاموس العصر ی میں (جوانگریزی اورعربی کی اچھی لغت ہے )مجنون کے معنے میں لکھاہے:.MAD, CRAZY, INSANE, FOOL,FOOLISH ٌٍدیوانہ.کم عقل.پاگل.احمق.بے وقوف.مفردات میں ہے.اَلْجِنَّۃُ جَمَاعَۃُ الْجِنِّ قَالَ تَعَالٰی مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ.وَقَالَ تَعَالٰی وَجَعَلُوْا بَیْنَہٗ وَبَیْنَ الْجِنَّۃِ نَسَبًا.جِنَّۃٌ کے دومعنے ہیں.ایک یہ کہ لفظ جن ّ کی جمع ہے جیسا کہ قرآن کریم کی مذکورہ بالادو آیات سے ظاہر ہے یعنی مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِاورجَعَلُوْا بَیْنَہٗ وَبَیْنَ الْجِنَّۃِ نَسَبًا سےاور دوسرے معنےا س کے جنون کے ہیں.جیساکہ لکھاہے اَلْجِنَّۃُ.اَلْجُنُوْنُ وَقَالَ تَعَالیٰ مَابِصَاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّۃٍ.أَیْ جُنُوْنٍ.یعنی جِنَّۃٌ کے معنے جنون کے بھی ہیںجیساکہ قرآن کریم کی آیت مَابِصَاحِبِکُمْ مِنْ جِنَّۃٍ سے ظاہر ہے.وَالْجنُوْنُ حَائِلٌ بَیْنَ النَّفْسِ وَالْعَقْلِ اورجنون ایک قسم کی روک کانام ہے جوانسان کی طبیعت اور اس کی عقل کے درمیان پیدا ہوجاتی ہے.وَجُنَّ فُلَانٌ قِیْلَ اَصَابَہُ الْجِنُّ یعنی بعض لوگوں کاخیال ہے کہ جب جُنَّ فُلَانٌ کہا جائے.تواس کا مطلب یہ ہوتاہے کہ اسے جن چمٹ گئے ہیں.وَبُنِیَ فِعْلُہٗ عَلیٰ فُعِلَ کَبِنَائِ الاَ دْوَائِ نَـحْوُزُکِمَ لُقِیَ وحُـمَّ َّ اور جُنّ بصیغہ مجہول اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے اوربیماریوں کے لئے یہ صیغہ بالعموم استعمال ہوتاہے.مثلاً زکام والے لقوہ والے اورتپ والے کے متعلق زُکِمَ.لُقِیَ اورحُـمَّ َّ استعمال ہوتاہے.وَقِیْلَ اُصِیْبَ جَنَانُہُ.اوربعض
Page 212
لوگوں کاخیال ہے کہ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے دل کو صدمہ پہنچ کر عقل ماری گئی ہے.وَقِیْلَ حِیْلَ بَیْنِ نَفْسِہِ وَعَقْلِہِ فَـجُنَّ عَقْلُہٗ بِذَلِکَ.اوربعض لوگوں کایہ خیال ہے کہ اس کے اور اس کی عقل کے درمیان کوئی روک پیداہوگئی ہے.اس وجہ سے وہ عقل سے کام نہیں لے سکتایہ مفردات والے نے مختلف لوگوں کاخیال جنون کی ماہیت کے متعلق بتایاہے اوراس سے ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ جب کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ مجنون ہے توعربی زبان میںاس کے یہی معنے ہوں کہ اسےجن چمٹ گیابلکہ اس کے اصل معنے تویہی ہوںگے کہ اس کادماغ خراب ہوگیاہے.باقی بعض لوگ جو وہمی ہیں جنون کی تشریح یہ کریں گے کہ کسی جن نے ناراض ہوکر اس کادماغ خراب کردیاہے.بعض لوگ جو احساسات کو بیماریوں کامنبع قرار دیتے ہیں یہ کہیں گے کہ اس کے دل کوکوئی صدمہ پہنچاہے اوربعض لوگ جوطبیعی ہیں یہ قرار دیں گے کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہوگیاہے.غرض کہ جنون کے معنے جن چمٹ جانے کے نہیں بلکہ جنون کاسبب بعض کے نزدیک جن کاچمٹ جاناہے.وَقَوْلُہُ مَعَلَّمٌ مَجْنُوْنٌ أَیْ ضَامَّہُ مَنْ یُعَلِّمُہُ مِنَ الْجِنِّ وَکَذَالِکَ قَوْلُہُ تَعَالیٰ اَئِنَّا لتَارِکُوْا اٰلِھَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُوْنٍ قرآن مجید کی آیت مُعَلَّمٌ مَجْنُوْنٌ اور لشَاعِرٍ مَجْنُوْن میں مجنون کے معنےمَنْ یُّعَلِّمُہُ الْجِنُّ کے ہیں یعنی جسے جن سکھاتے ہیں.(مفردات کے یہ معنے تفسیری ہیں یعنی مختلف تفاسیر کے اثر کے نیچے انہوں نے یہ معنے لکھ دئیے ہیںورنہ محقق لغت میں یہ معنی نہیں.لغت میں مجنو ن کے معنے یہی ہیں.کہ جسے جنون کی بیماری ہو).تفسیر.پہلے فرمایاتھا.رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَکہ بارہاکفار مسلم ہونے کی خواہش کریں گے.اب فرمایاکہ کفار اس بات کو سن کر کہ وہ ہلاک کردئیے جائیں گے نہایت تعجب کریں گے اور کہیں گے کہ تُوضرور پاگل ہے.جوایسی باتیں کرتا ہے ہم توجلد ہی تجھے اورتیرے متبعین کو کچل ڈالیں گے.رُبَمَاکے معنے مستقبل کے لینے کی صورت میں اس آیت کے معنے ربماکے معنے مستقبل کے کئے جائیں اوریہ مراد ہوکہ اسلام کی ترقیات کو دیکھ کر کفار کبھی کبھی یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے یاکاش ہم مسلمانوں کامقابلہ نہ کرتے یاکاش ہم اللہ تعالیٰ کے توکل پر عمل پیراہوتے تو اس صورت میں آیت کایہ مطلب ہوگا کہ جب کفار اس اعلان کو سنتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام کی ترقی کودیکھ کر کفار کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے تو وہ اس دعویٰ کو مجنونانہ قرار دیتے ہیں اورکہتے ہیں کہ تو پاگل ہے جو ایسے دعوے کرتاہے.ہم اسلام کے دشمن ایسی خواہش کس طرح کرسکتے ہیں اور ایسی ترقی تجھے اور تیرے اتباع کو کب مل سکتی ہے.الذِّكْرُ قرآن مجید کا نام ہے اس آیت میںالذِّكْرُ کالفظ آیاہے یہ قرآن مجیدکانام کفار میں بھی معروف
Page 213
معلوم ہوتاہے.ذکرکے معنی شرف کے ہوتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ آتاہے.لَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَیْکُمْ کِتَابًا فِیْہِ ذِکْرُکُمْ (انبیاء :۱۱) ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری عزت کے سامان ہیں چونکہ اس جگہ اسلام کی ترقی کا ذکر ہے اورکفار کی ذلت کا.اس لئے کفار طنزاً الذکر کے لفظ سے قرآن کا ذکرکرتے ہیں اورمطلب یہ ہے کہ ’’اے وہ شخص! جس پرایسامعزز اورممتاز کلام اُتراہے کہ ہم جیسے بھی خواہش کریں گے کہ ہم اس کے ماننے والے ہوتے.توپکاپاگل ہے ‘‘.بظاہر اس کلام کاپہلاحصہ دوسرے کے خلاف ہے ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص! جس پر یہ دنیاکو عزت دینے والا کلام نازل کیاگیاہے اوردوسری طرف کہتے ہیں کہ تو پاگل ہے.کفار الذِّكْرُ کا لفظ طنزًا کہتے ہیں مگرطنزیہ کلام کی صورت میں یہ اختلاف باقی نہیں رہتا.یہ فقرہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوزخیوں کے متعلق آتاہے کہ ذُقْ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْکَرِیْمُ (الدخان :۵۰) اے معززاورشریف انسان! دوزخ کاعذاب چکھ.یعنی تم اپنے آپ کو عزیز و کریم کہتے تھے.اب دیکھو کہ تمہاری عزت اورکرم نے تم کوکس حالت تک پہنچادیاہے؟ اِنَّکَ لَمَجْنُوْنٌ سےعیسائیوں کا اعتراض اِنَّکَ مَجْنُوْنٌ اس کے متعلق عیسائیوں نے اعتراض کیاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرورکوئی جنون کامادہ تھاورنہ عرب لوگ آپؐ کو کیوں مجنون کہتے.اچھے بھلے آدمی کو کون پاگل کہتاہے.مجنون کے معنوں کی تعیین میں عیسائیوں کی غلطی اس اعتراض کے بیان میں انہوں نے پہلے تو مجنون کے معنوں کی تعیین میں غلطی کی ہے.سیل اس آیت کاترجمہ یوں کرتاہے.THOU ART CERTAINLY POSSESSED BY A DEVIL ضرور تجھ پر کوئی شیطان قابض ہے.(تفسیر القرآن از وہیری) روڈویل اس کاترجمہ یوں کرتاہے :.THOU ART SURELY POSSESSED BY A JINN تجھ پر یقیناً کسی جن کاسایہ ہے.(ترجمۃ القرآن از روڈویل) پامر لکھتاہے :.VERILY THOU ART POSSESSED
Page 214
توتو بُری روحوں کے قبضہ میں ہے.(ترجمۃ القرآن از ای.ایچ پامر) مجنون کے معنے دیوانہ یا پاگل کے ہوتے ہیں گویامجنون ان کے نزدیک وہ شخص ہوتاہے جس پر کوئی شیطان یاجن قابض ہو.حالانکہ اس جگہ یہ معنی مراد نہیں ہوسکتے.اورنہ ہیں.بلکہ جیساکہ اوپر حل لغات میں بتایاگیاہے مجنون کے معنے پاگل یادیوانہ ہوتے ہیں.مجنون کے معنے اقرب الموارد میں لکھے ہیں.مَنْ زَالَ عَقْلُہَ اَوْفَسدَ جس کی عقل جاتی رہے یاعقل میں خرابی آجائے.(تفصیل کے لئے دیکھو حل لغات) آنحضرت ﷺ پر عیسائیوں کا الزام اپنے عیب کو چھپانے کے لئے ہے اصل میں یوروپین مصنفین نے اپنے عیب کو چھپانے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے یہ الزام لگانے کی کوشش کی ہے.کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ یہودی حضرت مسیح ؑ کو کہتے تھے کہ اس پر جن سوار ہے.مگر انہوں نے اتناغو رنہ کیاکہ وہاں کہنے والے یہودی ہیں اوراس جگہ مشرکین.یہودیوں کے نزدیک تو جنّ ایک ناپاک روح ہےجس پروہ سوار ہواس کے معنے ہیں کہ وہ گنداہے مگرمشرکین کے ہاں تو جنّوں کی پوجاکی جاتی تھی.اگرکفار کایہی مطلب ہوتا تووہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرتے بلکہ آپؐ سے ڈرتے.عیسائی معترضعین کا غلط استدلال پھر عیسائی معترضین نے دوسراظلم یہ کیاہے کہ وہ لکھتے ہیں.کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہلِ مکہ جومجنون کہتے تھے اس کاضرور کوئی سبب چاہیے اوروہ سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپؐ کو نَعُوْذُبِاللہِ مِنْ ذَالِکَ مرگی کے دورے پڑتے تھے.ا س کی تائید میں انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاوہ واقعہ نقل کیاہے جو آپؐ کو حلیمہ دائی کے ہاں بقول بعض مؤرخین پیش آیاتھا.وہ واقعہ اس طرح بیان ہواہے کہ آپؐ نے جنگل میں دیکھا (جہاں بعض بڑے بچے جانور چرارہے تھے )کہ دوآدمی براق لباس پہنے ہوئے آئے ہیں.انہوں نے آپؐ کو گرالیا اورآپ ؐ کے سینہ کو چاک کیا اورکوئی سیاہ سی چیز اندرسے نکال کر پھینک دی (مسند احمد بن حنبل ، مسند الشامیین حدیث عقبۃ بن عبد السلمی).عیسائی اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بچے تھے اس لئے جھوٹ تونہیں بولتے تھے لہٰذامرگی کادورہ مانناپڑے گا.میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑتا کہ مرگی کے دورہ میں انسان اس قسم کے واقعات اورنظارے دیکھتاسوچتااورانہیں یاد رکھ سکتاہے یاکہ نہیں میں نے ڈاکٹری کتابیں دیکھی ہیں.جن میں اس مرض کی اقسام اوران کی کیفیات بیان ہیں ان میں یہ ہرگز نہیں لکھا کہ انسان اس دورے کی حالت میں کسی نظارہ کو دیکھ کرباترتیب یاد رکھ
Page 215
سکتاہے اورپھر مرگی کے دورے والے کی آنکھیں شکل اورعقل اور دوسرے حالات سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ مرگی کامریض ہے.بلاوجہ معمولی سی تکالیف کو باربار دوہرانا.خالی الذہن نظر آنا.اورمعمولی معمولی باتوں پر غصہ کرنا ایسے شخص کی عادت میں داخل ہو جاتا ہے.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی کوئی بات پائی نہ جاتی تھی.یسوع کو لوگ آسیب زدہ کہتے تھے عیسائی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی وجہ نہ تھی توساری قوم انہیں کیوں مجنون کہہ رہی تھی.میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں یسوع نامی ایک اورآدمی بھی پیدا کیاہے.جس کولوگ آسیب زدہ قراردیتے تھے اورمجنون کہتے تھے.چنانچہ (یوحنا باب ۱۰ آیت ۱۹،۲۰)میں لکھا ہے.کہ ’’ان باتوں کے سبب یہودیوں میں پھر اختلاف ہوا.ان میں بہتیرے توکہنے لگے کہ اس میں بدروح ہے.اوروہ دیوانہ ہے.تم اس کی کیوں سنتے ہو.‘‘اس بزرگ کے ایک شاگرد پولوس نامی کی نسبت بھی لکھاہے.’’جب وہ اس طرح جوابدہی کررہاتھا.توفیتس نے بڑی آواز سے کہا.اے پولوس توُدیوانہ ہے.بہت علم نے تجھے دیوانہ کردیاہے.‘‘(اعمال باب ۲۶ آیت ۲۴) اب عیسائیوں کوچاہیے کہ وہ پہلے مسیح ؑ اورپولوس کو دیوانہ کہنے کاسبب مرگی کادورہ ثابت کریں اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف توجہ کریں.کیونکہ اپنے گھرکاکام مقدم ہوتاہے.مسیحی معترضین کے اعتراض کا بطلان کاش یہ مسیحی معترضین انصاف سے کام لیتے.اور غور کرتے.تو اگر حضرت مسیح ؑکو بغیر مرگی کے دوروں کے صرف وعظ سن کر پاگل کہاجاسکتاہے توکیوں رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ کے عظیم الشان دعویٰ کرنے والے کو روحانی عالم سے ناواقف لوگ پاگل نہیں کہہ سکتے تھے.مسیحیوں کایہ اعتراض اور بھی قابل تعجب ہو جاتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات میں کفار کی پیش کردہ وجہ بھی بیان ہے جس کی بنا پر وہ آپؐ پر جنون کاالزام لگاتے تھے.وہ اس الزام کی وجہ مرگی کو بیان نہیں کرتے.بلکہ آپؐ کے دعاوی کے بعید ازعقل ہونے کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں اوریہ بات ہر نبی میں پائی جاتی ہے.کوئی نبی نہیں جس نے وہ باتیں نہ کی ہوں جن کو اس زمانہ کے لوگ ماننے کو تیار نہ تھے.
Page 216
لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓىِٕكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۰۰۸ اگرتوسچا ہے توکیوں ملائکہ کو ہمارے سامنے نہیں لاتا.حلّ لُغَات.لَوْ مَا لَوْمَااور لَوْ لَا اور ھَلَّا ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں.یہ نحاس کاقول ہے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کیوں ایسانہیں کرتے.مطلب یہ کہ ایساکرو.(تفسیر القرطبی تفسیر سورۃ الحجر زیر آیت ھٰذا) تفسیر.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کادعویٰ گزشتہ سورتوں میں یہ پیش کیاگیاتھااوراس سورۃ کاشروع بھی اسی تسلسل میں تھاکہ اسلام کی فتح اس کلام کے ذریعہ سے ہوگی.جو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے.وہ کلام اپنے اندر ایسی خوبیاں رکھتاہے کہ اس کے مقابل پر کفار کازورنہ چل سکے گا.کفار کا لاجواب ہو کر آنحضرت ﷺ کو مجنون کہنا کفارنے اس دعویٰ کے بالمقابل لاجواب ہوکریہ دعویٰ پیش کردیاکہ تم تومجنون ہو اورمجنون ہونے کی یہ دلیل دی کہ تم کہتے ہوکہ یہ کلام تم پرفرشتے لے کرآتے ہیں.اگر تمہارایہ قول درست ہوتاتوپھر وہ فرشتے دوسرے لوگوں کوبھی نظر آتے.لیکن چونکہ وہ دوسرے لوگوںکو نظر نہیں آتے.معلوم ہواکہ یہ تمہاراوہم ہے.اور تمہارے جنون کی علامت ہے.مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰٓىِٕكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَا كَانُوْۤااِذًا مُّنْظَرِيْنَ۰۰۹ (کیاا نہیں معلوم نہیں کہ)ہم (جب بھی )فرشتوں کو( اتارتے ہیںتو) حق کے مطابق اتارتے ہیں اور(جب کافروں کے لئے اتارتے ہیں تو)اس وقت انہیں (ذرّہ بھی )مہلت نہیں دی جاتی.حل لغات.حَقّ کی تشریح کے لئے دیکھیںسورۃ رعد آیت نمبر۱۵.مُنْظَرِیْنَ.اَنْظَرَہُ الدَّیْنَ.اَخَّرَہٗ.قرض اداکرنے کے لئے قرض دار کومزید مہلت دی.یُقَال کُنْتُ اُنْظِرُ الْمُعْسِرَ اَیْ اُمْھِلُہُ یعنی کُنْتُ اُنْظِرُ الْمُعْسِرَکافقرہ انہی معنوں کے لئے استعمال ہوتاہے کہ میں تنگدست قرض دار کو مہلت دیاکرتاتھا.(اقرب) تفسیر.بِالْحَقِّ کے تین معنے حَقّ کے معنے پہلے گزرچکے ہیں اس جگہ یاتواس کے معنے سچے کلام کے ہیں اورمطلب یہ ہے کہ فرشتے کلام الٰہی کے ساتھ اُتراکرتے ہیں.مگرتم نہ رسول ہوکہ تم پر فرشتے اتریںاورنہ ہی
Page 217
تم اس بات کے مستحق ہوکہ تمہیں کلام الٰہی سے مشرف کیاجائے یا اس جگہ پر حق کے معنے استحقاق کے ہیں.یعنے جیسا جیساکسی کاحق ہو اس کے مطابق فرشتے اُترتے ہیں.اللہ تعالیٰ کے نبیوں اورمومنوں پر ان کے حق کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرجوفرشتے اترتے ہیں وہ تو رحمت کے فرشتے ہیں وہ محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نظر آسکتے ہیں.وہ ان خدا تعالیٰ کاغضب سہیڑنے والوں کو کس طر ح نظر آجائیں ان پرتوجب فرشتے اتریں گے غضب ہی کے اتریں گے اوراس وقت فرشتوں کادیکھنا انہیں نفع نہ دےگا کیونکہ وہ ان کے ہلاک کرنے کے لئے آئیں گےاوران کے آنے کے بعد آئمۃ الکفر کو ڈھیل نہ ملے گی.چنانچہ بدرکے موقعہ پر یہ سزادینے والے فرشتے آئے اوربعض کفار کو کشفی حالت میں وہ نظر بھی آئے مگروہ وقت ان کی ہلاکت کا تھا ان سے وہ کیافائدہ اٹھاسکتے تھے ؟ (سیرۃ النبویۃ لابن ہشام باب غزوۃ بدرشہو د الملا ئکۃ وقعۃ بدر) ملائکہ کا کلام انسان کے قلب کے مطابق ہوتا ہے اس جگہ ایک بہت بڑانکتہ بیان فرمایاگیاہے وہ یہ کہ ملائکہ کاکلام انسان کے قلب کے مطابق ہوتاہے جیسا انسان ہوگاویسے ہی اس کے الہام ہوںگے.عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الہام ہوگیاتوہم بڑے آدمی ہوگئے حالانکہ یہ کافی نہیں کیونکہ الہام انسان کی اپنی فطرت کے مطابق ہی ہواکرتاہے.پہاڑی مزدور کا واقعہ قادیان میں ایک پہاڑی شخص مزدوری وغیرہ کی غرض سے آیا کرتاتھاوہ عموماً ہمارے ہاں ہی مزدوری وغیرہ کرتاتھابعض اوقات کسی کام کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح اوّلؓ کے پاس چلاجاتا توحضرت خلیفۃاوّل ؓ اسے نماز کی تاکید فرمایاکرتے تھے جس پر وہ جواب دیاکرتاکہ ’’نماز سانوں پجدی نیئں ‘‘(یعنی نماز ہمارے مناسب حال نہیں ) اتفاقاً ایک روز آپ نے اسے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا.فراغت کے بعد پوچھاکیابات ہے؟تواس نے جواب دیاآج مجھے الہام ہواہے کہ ’’اُٹھ اوئے سورانماز پڑھ ‘‘اَے سوَر اٹھ کرنماز پڑھ.اس لئے میں نے نماز شروع کردی ہے.اب ظاہر ہے کہ یہ الہام شیطان کی طرف سے توہونہیںسکتایہ یقیناً خدائی الہام تھا مگر اس کے درجہ کے مطابق تھا.پس خالی الہام کونہیں دیکھاجائے گا بلکہ یہ دیکھاجائے گاکہ اس الہام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیامحبت کابھی اظہارہے یا اس بندے کی شان کے اظہار کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس آیت سے ایک عام قانون کاپتہ چلتاہے اوروہ یہ کہ فرشتے بالحق نازل ہواکرتے ہیں.یہ امر ظاہر ہے کہ مومنوں میں ادنیٰ ،اعلیٰ ،مامور وغیر مامور سب ہی شامل ہیں.اسی طرح نبیوں میں مرتبہ کاتفاوت پایا جاتا ہے حضرت خاتم النبین علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی طرح نبی کہلاتے ہیں جس طرح زکریا،الیاس اوریوسف علیہم السلام.
Page 218
پس جس طرح درجہ میں نام کی شرکت سب کو برابر نہیں بنادیتی اسی طرح سب کی وحی وحی کہلا کر ایک سی نہیں ہوسکتی.ہر ایک نبی کا کلام اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے ہرایک نبی کاکلام اس کی شان کے مطابق ہوگا.اس اصل کو مدّنظررکھیں تویہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ تورات ،انجیل، زبور وغیرہ کیوں قرآن کریم کی طرح بے نظیر نہیں.جن انبیاء پر وہ کلام نازل ہوئے انہی کی شان کے مطابق ان میں خدا تعالیٰ نے برکت رکھی.یہ کس طرح ہوسکتاتھاکہ اللہ تعالیٰ مختلف درجوں کے کام مختلف نبیوں کے سپرد کرتالیکن سامان سب کو ایک سادیتا بہرحال کام کے مطابق ہی اس نے سامان دینے تھے اورکام کے مطابق ہی اس نے کارکن مقررکرنے تھے.اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۰۰۱۰ اس ذکر کو ہم نے ہی اُتاراہے اورہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے حلّ لُغَات.الذِّکْرَ کی تشریح کے لئے دیکھیں حل لغات سورۃ ہذاآیت نمبر ۷ و یوسف آیت نمبر ۱۰۵.تفسیر.ذکر کے معنے بتائے جاچکے ہیں کہ علاوہ اورمعنوں کے اس لفظ کے معنے شرف اورنصیحت کے بھی ہیں.اس جگہ یہی معنے ہیں کفار نے طنزاً کہاتھا.کہ اے وہ شخص! جس پر یہ عزت بخش کلام نازل ہواہے.تویقیناً مجنون ہے.اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے.یقیناً ہم نے ہاں! ہم نے اس عزت بخش کلام کو نازل کیاہے.آیت کا پہلی آیت سے تعلق یہ ایک نہایت ہی زبردست آیت ہے.اورایسی عجیب ہے کہ اکیلی ہی قرآن مجید کی صداقت کابیّن ثبوت ہے.اس میں کتنی تاکیدیں کی گئی ہیں.پہلے اِنَّ لایاگیاہے پھر نا کی تاکید نَحْن سے کی گئی ہے.اورپھر آگے چل کر ایک اور اِنََّّ اورلام لایاگیاہے.گویاتاکید پر تاکید کی گئی ہے.کفّار نے اِنَّکَ لَمَجْنُوْنٌ کے جملہ میں دوسری تاکید سے کام لے کر تمسخر کیاتھا.اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ تاکید کے چار ذرائع استعمال کرتاہے.اورفرماتا ہے.اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ سنو!ہم نے ہاں! یقیناً ہم نے ہی اس شرف و عزت والے کلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اُتاراہے اور ہم اپنی ذات کی قسم کھاکرکہتے ہیں کہ یقیناً ہم اس کی خود حفاظت کریں گے.اللہ اللہ کتنا زور ہے کس قدر حتمی وعدہ ہے!! اس آیت کے متعلق یہ لطیفہ بھی یادرکھنے کے قابل ہے کہ کفا رکے طنز میںایک یہ معنے بھی پائے جاتے ہیں کہ ایسا بڑازبردست کلام جس نے دنیاکوشرف بخشناہے اس کے ساتھ توفرشتے بھی آنے چاہیے تھے.اللہ تعالیٰ
Page 219
فرماتا ہے کہ اے نادانو!تم فرشتے کہتے ہواس کلام کی تووہ عظمت ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے ہم خود آئیں گے اوردیکھیں گے کہ کون اس کلام پر بدنیتی سے ہاتھ ڈالتاہے.اس کایہ مطلب نہیں کہ فرشتے قرآن کریم کی حفاظت نہیں کرتے.کیونکہ جب خداجوآقاہے وہ حفاظت کرتاہے توفرشتے توبدرجہ اولیٰ حفاظت کریں گے مگر اِنَّالَہُ لَحٰفِظُوْنَ فرماکر ایک زائد بات بیان کی کہ اس میں بعض ایسی خصوصیات ہیں جن کی حفاظت فرشتے بھی نہیں کرسکتے.بلکہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمّے لی ہے.ہرچیز کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں.مگرخدا تعالیٰ کے براہِ راست حفاظت کرنے میں ایک حکمت ہے اورقرآن مجید کو عام چیزوں سے ممتاز کرنے والافرق ہے جسے میں آگے چل کر بیان کروں گا.یہ آیت اسلام کی صداقت کاایک زبردستثبوت ہے اوراگر کوئی بے تعصب انسان اس آیت پر غور کرے تو سمجھ سکتاہے کہ یہ دعویٰ انسانی نہیں.تمام مفسّر متفق ہیں کہ یہ سورۃ مکی ہے.ابن ہشام کابیان ہے کہ یہ آیت دعویٰ نبوت کے چوتھے سال میں نازل ہوئی.انگریز مصنف عام طور پر اس بات کے شائق ہوتےہیں کہ وہ مسلمان مفسرین سے اختلاف کریں اور اس کے لئے انہوں نے ایک انٹرنل شہادت(اندرونی شہادت)کا قاعدہ بنارکھاہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن کے اندرسے نکلتی ہے.مگروہ اس طریق کو ایساغلط اوربے جااستعمال کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتاہے.کہ یہ اندرونی شہادت قرآن کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے نفس کی ہوتی ہے.مگراس ضمن میں مجھے انگریزی حوالے دیکھتے ہوئے یہ دیکھ کرخوشی ہوئی کہ اس بارہ میں مستشرقین کوبھی اختلاف کی گنجائش نہیں ملی.چنانچہ سپرینجرنے کہا ہے.کہ یہ سورۃ دعویٰ نبوت کے چوتھے سال میں نازل ہوئی تھی.روڈویل جس نے ترتیب کی تحقیق کے متعلق بزعم خودایک کمال حاصل کیاہے.لکھتاہے کہ یہ سورۃ ابتدائی سالوں کی سورتوں میں سے ہے.چنانچہ اس نے اپنی ترتیب میں اسے ابتدائی سالوں کی سورتوں میں ہی رکھاہے.نولڈک نے کسی قدراختلاف کیاہے اوراس کی بنیاد وہی غلط قاعدہ (انٹرنل شہادت کا)ہے.وہ لکھتاہے کہ :.(۱) اس میں کفار کی سختیوں کا ذکر ہے اس لئے یہ ابتدائی سالوں کی سورۃ نہیں ہوسکتی (۲) اس میں یُسَبِّحُ بِحَمْدِہٖ آتاہے.یہ باقی ابتدائی سورتوں میں نہیں آتا.لہٰذایہ بھی ابتدائی زمانہ کی نہیں (۳)اس میں مشرکین کالفظ ہے اس لئے یہ ابتدائی زمانہ کی نہیں ہوسکتی ہاں مکّی ضرور ہے.مکی زندگی کے آخری ایام میں اُتری ہے.مجھے اس سے بحث نہیں کہ نولڈک کی بات درست ہے یادوسروں کی.مَیں صر ف یہ بتاناچاہتاہوں کہ نئی تحقیق
Page 222
غلطیاں (طرز تحریر)ہوں تو ہوں.لیکن جو قرآن عثمانؓ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھااس کامضمون وہی ہے جو محمد(صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ) نے پیش کیاتھا.گو ا س کی ترتیب عجیب ہے.یوروپین علماء کی یہ کوششیں کہ وہ ثابت کریں کہ قرآن میں بعد کے زمانہ میں بھی کوئی تبدیلی ہوئی ہے بالکل ناکام ثابت ہوئی ہیں.(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ قرآنKoran ) یہ و ہ شہادتیں ہیں جو اسلام کے شدید ترین دشمنوں کی ہیں.اوراَلْفَضلُ مَا شَھِدَتْ بِہٖ الْاَعْدَاءَ.قرآن مجید کے منجانب اللہ ہونے پر کتنی بڑی شہادت ہے کہ قرآن کریم امّیوں میں آتاہے اورہرطرح سے محفوظ رہتاہے مگرتورات اور انجیل اپنے زمانہ کی علمی قوموں میں آئیں لیکن محفوظ نہ رہ سکیں.میور اس کے متعلق کیا ہی پُرحسرت الفاظ لکھتاہے." TO COMPARE THERE PURE TEXTS WITH THE VARIOUS READINGS OF OUR SCRIPTURES IS TO COMPARE THINGS BETWEEN WHICH THERE IS NO ANALOGY." قرآن مجید کے غیر محرف ہونے کے متعلق میور کا اعتراف ترجمہ :مسلمانوںکی بالکل پاک اور غیرتبدیل شدہ کتاب اورہماری کتب کے مختلف نسخوں کے باہمی اختلاف کامقابلہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ دو ایسی چیزوں کامقابلہ کیاجائے جن میں باہمی کوئی بھی مشابہت نہیں.(لائف آف محمد صفحہ ۵۵۸) قرآن شریف کا محفوظ ہونا اتفاقی بات نہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ قرآن شریف آج تک محفوظ ہے ؟اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ اس کی ظاہر حفاظت الکتاب اور قراٰن مبین کے دوذریعوں سے ہوتی ہے جن کا ذکر اس سورۃ کے شروع ہی میں کیا گیاہے.شروع نزول ہی سے ا س کی آیات لکھی جانے لگیں اوراس کی حفاظت ہوتی گئی اورپھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے عشاق عطاکئے جو اس کے ایک ایک لفظ کو حفظ کرتے اوررات دن خود پڑھتے اوردوسروں کو سناتے تھے.اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کسی نہ کسی حصے کا نمازوں میں پڑھنا فرض مقررکردیا اورشرط لگادی کہ کتاب میں سے دیکھ کر نہیں بلکہ یاد سے پڑھاجائے.اگر کوئی کہے کہ یہ محمدؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو ایک بات سوجھ گئی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہی بات زرتشت ،موسیٰ اوروید والوں کو کیوں نہ سوجھی.معلوم ہوتاہے کہ اس کا سوجھانے والا کوئی اورہے.کولمبس جب امریکہ کو دریافت کر کے واپس آگیا تولوگوں نے کہا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے ہم جاتے توہم بھی امریکہ کو دریافت کرلیتے.مگرکولمبس نے
Page 223
اس کے جواب میں ایک انڈادے کر کہا کہ تم یہ انڈامیز پر کھڑاکردوسب نے کوشش کی مگروہ کھڑانہ ہوا.آخر میں کولمبس اُٹھا اور اُس نے ایک سوئی سے اس میں چھید کیا اور اس سے جو لعاب نکلا اس کی مدد سے اسے میز پر کھڑاکردیااس پر لوگوں نے کہا کہ ایساتو ہم بھی کرسکتے تھے کولمبس نے کہا کہ امریکہ کی دریافت کے بارہ میں تو تم نے کہہ دیاکہ ہمیں موقع نہیںملامگر اس بارہ میں تو تم کو موقعہ مل گیاتھا کیوں نہ تم نے اپنی عقل سے کام لیا.پس ایسا ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ ذرائع حفاظت کے جو قرآن کے بارہ میں استعمال کئے گئے آخر کیوں قرآن کریم کے پیش کرنے والے کو ہی سوجھے کیوں دوسری جماعتوں نے اسے استعمال نہ کیا؟ یہ بھی یا د رہے کہ ایسے آدمیوں کامیسر آنا جو اسے حفظ کرتے اورنمازوں میں پڑھتے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی طاقت میں نہ تھا.ان کامہیا کرنا آپؐ کے اختیار سے باہر تھا.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ کہ ایسے لوگ ہم پیداکرتے رہیں گے جو اسے حفظ کریں گے.آج اس اعلان پر تیرہ سو سال ہوچکے ہیں اورقرآن مجید کے کروڑوں حافظ گذر چکے ہیں بعض یوروپین ناواقفیت کی وجہ سے کہہ دیاکرتے ہیں کہ اتنا بڑاقرآن کس کو یاد رہتاہوگامگر قادیان ہی میں کئی حافظ مل سکتے ہیں جنہیں اچھی طرح سے قرآن یاد ہے چنانچہ میرے بڑے لڑکے ناصر احمد سلمہ اللہ تعالیٰ نے بھی گیارہ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرلیاتھا.قرآن مجید ایسے الفاظ میں نازل ہوا ہے کہ وہ سہولت سے یاد ہو جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجیدکو اپنے خاص تصرف سے ایسے الفاظ اورایسی ترکیب سے نازل فرمایا ہے کہ وہ سہولت سے حفظ ہو جاتا ہے.قرآن شعر نہیں مگرشعر سے بھی زیادہ جلد یاد ہو جاتا ہے.اردویاانگریزی کی عبارتوں کی نسبت قرآن شریف کے حفظ کرنے پرنصف وقت بھی صرف نہیں ہوتا.ایک انگریزمترجم قرآن لکھتاہے کہ قرآن ایسی عبارت میں ہے کہ اس کو بغیر ترتیل کے پڑھنے کے چارہ ہی نہیں.پس قرآن مجید کی زبان ان اللہ تعالیٰ کے پیداکردہ سامانوں میں سے ہے جن کے ذریعہ سے قرآن مجید کی حفاظت کی جاتی ہے.قرآن مجیدکی حفاظت کے چار سامان سب سے اول اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمیوں کو پیدا کیا جو اسے شروع سے لے کر آخر تک حفظ کرتے تھے.دوسرے اس کی زبان ایسی سہل اوردلنشین بنائی کہ سہولت سے یاد ہوجائے.سوم اس کی تلاوت نمازوںمیں فرض کردی.چہارم لوگوں کے دلوں میں اس کے پڑھنے کی غیر معمولی محبت پیداکردی.
Page 224
قرآن کریم کو بغیر معنے پڑھنے پر عیسائیوں کا اعتراض اور اس کا جواب عیسائی لوگ ہمیشہ اعتراض کیاکرتے ہیں کہ مسلما ن قرآن کریم کوبے معنی ہی پڑھتے رہتے ہیں.اس کے معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن اگر غورکیاجائے تویہ بھی ا س آیت میںمذکور وعدہ کی تصدیق ہے.مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن کریم کی محبت ڈال دی ہے کہ معنی آئیں یا نہ آئیں وہ اسے پڑھتے چلے جاتے ہیں.یقیناً ہرمسلمان کافرض ہے کہ قرآن کریم کو بامعنی پڑھے اوراس طرف سے تغافل بڑی تباہی کاموجب ہواہے.مگر باوجود معنے نہ جاننے کے مسلمانوں کاقرآن کریم کو یاد کرتے چلے جانایقیناً اس آیت میں مذکور وعدہ کے پوراہونے کی دلیل ہے.آج اگر بائیبل کے سارے نسخے جلادیئے جائیں توبائبل کے پیرواس کابیسواں حصہ بھی دوبارہ جمع نہیں کرسکتے لیکن قرآن مجید کو یہ فخر حاصل ہے کہ اگر(بفر ض محال)سارے نسخے قرآن مجید کے دنیا سے مفقود کردیئے جائیں تب بھی دوتین دن کے اند ر مکمل قرآن مجید موجود ہو سکتا ہے.اوربڑے شہر تو الگ رہے ہم قادیان جیسی چھوٹی بستی میں اسے فوراً حرف بحرف لکھواسکتے ہیں.دنیا کی کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں کہ جسے مٹادیاجائے اوروہ پھر بھی محفوظ رہے سوائے قرآن پاک کے.ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لئے یہ مقرر فرمایاکہ ایسے سامان کردیئے کہ قرآن مجید اپنے نزول کے معاً بعد تمام دنیا میں پھیل گیااوراب اس میں تغیروتبدل کاامکان ہی نہیں رہا.کہاجاتاہے کہ ایک مرتبہ روسی حکومت نے ارادہ کیاکہ جہاد کی آیات نکال کر قرآن چھپوائیں مگر اسے بتایاگیاکہ قرآن مجید تو تمام دنیا میں پھیلاہواہے اوریہ آیات ہرجگہ موجود ہیں پھر تم ان کو کیسے نکال سکو گے.اس سے وہ اپنے ارادوں سے باز رہی.ایک ذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کا یہ تھا کہ اسلامی علوم کی بنیاد قرآن مجید پر قائم ہوئی.اس ذریعہ سے اس کی ہرحرکت و سکون محفوظ ہوگئے مثلاً نحو پیداہوئی توقرآن مجید کی خدمت کے لئے چنانچہ نحو کے پیدا ہونے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ابوالاسوددئولی حضرت علیؓ کے پاس آئے کہ ایک نیا مسلمان’’اِنَّ اللّٰہَ بَرِیْءٌ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَرَسُوْلُہٗ‘‘کی بجائے وَرَسُوْلَہٖ پڑھ رہاتھاجس سے ڈرہے کہ نو مسلموںکو قرآن مجید کے مطالب سمجھنے میں مشکل پیش آئے.حضرت علیؓاس وقت گھوڑے پر سوار جارہے تھے اسی حالت میں آپ انہیں بعض قواعد نحو بتاتے چلے گئے اورفرمایاکہ اسی قسم کے قواعد کو ضبط میں لے آئو.اس سے ان نومسلموں کوصحیح تلاوت کی توفیق ملے گی اور کچھ قواعد بناکر فرمایا اُنْـحُ نَحْوَہٗ یعنی اسی رنگ میں اورقواعد تیار کرلو.اس فقرہ کی وجہ سے عربی گریمر کانام نحو پڑ گیا.پھر مسلمانوں نے تاریخ ایجاد کی توقرآن مجید کی خدمت کی غرض سے کیونکہ قرآن مجید میں مختلف اقوام کے حالات آئے
Page 225
تھے.ان کو جمع کرنے لگے تو باقی دنیا کے حالات ساتھ ہی جمع کردیئے.پھر علم حدیث شروع ہواتوقرآن مجید کی خدمت کے لئے تامعلوم ہوسکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے کیامعنے کئے ہیں؟ قرآن مجید کی حفاظت کے لئے علوم کی تجدید پھر اہل فلسفہ کے قرآن مجید پر اعتراضات کے دفعیہ کے لئے مسلمانوں نے فلسفہ وغیرہ علوم کی تجدید کی اورعلم منطق کے لئے نئی مگر زیادہ محقق راہ نکالی.پھر طب کی بنیاد بھی قرآن مجید کے توجہ دلانے پر ہی قائم ہوئی.نحو میں مثالیں دیتے تھےتوقرآن مجید کی آیات کی.ادب میں بہترین مجموعہ قرآن مجید کی آیات کو قراردیاگیاتھا.غرض ہر علم میں آیاتِ قرآنی کو بطور حوالہ نقل کیاجاتاتھااورمیں سمجھتاہوں کہ اگر ان سب کتابوں سے آیات کوجمع کیاجائے تو ان سے بھی ساراقرآن جمع ہوجائے گا.مسلمانوں میں قرآن کریم کی خدمت کے لئے دوسرے علوم کی طرف رجوع کاایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہواکہ پہلی کتابوں سے تو دنیوی علماء کا طبقہ سخت بے زار تھا مگرمسلمانوں میں سے ان علوم کے ماہر ہمیشہ قرآ ن مجید کے خاد م رہے ہیںکیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سچے علوم کادشمن نہیں بلکہ مؤید ہے.قرآن مجید کی حفاظت کے لئے علمی عربی زبان کی تبدیلی بند ہوگئی ایک بہت بڑاذریعہ قرآن مجید کی حفاظت کایہ بھی ہواکہ نزول قرآن کے بعد علمی عربی زبان کی تبدیلی بند ہوگئی.عربی کے سوادنیا میں کو ئی ایسی زبان نہیں پائی جاتی جو آج بھی وہی ہو جس طرح تیرہ سو سال پہلے تھی چاسر اورشیکسپیر کی تین سوسال قبل کی انگریزی کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت بدل چکی ہے مگرقرآن مجید کے سمجھنے کے لئے پرانی لغتوں کی ضرورت نہیںکیونکہ جو شخص علمی عربی آج پڑھتاہے وہ قرآن کریم کو بھی بغیر کسی کی مددکے سمجھ سکتاہے.قرآن مجید کی حفاظت الہام کے ذریعہ ان ظاہری سامانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کاایک ایساذریعہ بھی مقرر کیاجس میں ملائکہ کا بھی دخل نہیں اوروہ الہام ہے.الہام میں ملائکہ بعض اوقا ت صرف پہنچانے والے ہوتے ہیں مگر انہیں اس کاسبب نہیں قرار دیاجاسکتا.قرآن مجید کی حفاظت مامورین اور مجددین کے ذریعہ حق یہ ہے کہ خدا کاکلام بندے کے ساتھ براہ راست ہوتاہے.ملائکہ صرف بطور واسطہ کے ہوتے ہیںاوراسی وجہ سے ’’اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ‘‘ کہہ کر یہ بتایاہے کہ ہم اس کلام کی آئندہ تازہ بتازہ الہام کے ذریعہ سے حفاظت کرتے رہیں گے یعنی مجدد اورمامور وغیرہ مبعوث کرتے رہیں گے.یہ ظاہر ہے کہ جس کتاب کے لفظ تو محفوظ ہوں.مگرمعنوں کی حفاظت نہ ہووہ محفوظ کتاب نہیں کہلاسکتی مثلاً وید
Page 226
ہیں اگریہ فرض بھی کرلیاجائے کہ وہ لفظاً محفوظ ہیں.توبھی وہ کتاب کامل ہونے کے لحاظ سے محفوظ نہیں کیونکہ جس زبان میں وہ نازل ہوئے ہیں وہ محفوظ نہیں رہی اس لئے اس کے معانی بالکل مشتبہ ہوگئے ہیں.اب اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پاکر کوئی شخص اس کے صحیح معانی نہ بتائے توکون یقین کے ساتھ کہہ سکتاہے کہ وہ اس کاصحیح مطلب بیان کررہاہے یااس کے مطابق عمل کررہاہے.یہ نقص اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد ایسے لوگ کھڑے ہوتے رہیں جو کتاب کے صحیح مفہوم کی طرف لوگوں کو لاتے رہیں اوریہ حفاظت دائمی طور پر قرآن کریم ہی کو حاصل ہے.بے شک دوسر ی کتب سماویہ کو بھی اُس عرصہ میں کہ وہ زندہ کتب تھیں یعنے دنیا کے لئے قابل عمل تھیں یہ حفاظت حاصل تھی مگر اب نہیں.اب صرف قرآن کریم ہی کو یہ حفاظت حاصل ہے صرف اس کے ماننے والے ہرزمانہ میں خدا تعالیٰ سے براہ راست الہام پانے کے مدعی ہوتے چلے آئے ہیں.قرآن مجید کی حفاظت کے لئے حضرت مسیح موعود کی بعثت اوراس زمانہ میں کہ دین سے غفلت انتہاکو پہنچ گئی ہے.اللہ تعالیٰ نے ایک ایسامامور مبعوث فرمایا ہے جس نے کلی طور پر قرآن کی تفسیروںکو زوائد اورحشو سے پاک کرکے اصلی صورت میں دنیاکے سامنے پیش کیاہے حتیٰ کہ قرآن جو اسی زمانہ کے علوم کے سامنے ایک معذرت خواہ کی صورت میں کھڑاتھا.اب ایک حملہ آور کی صورت میں کھڑاہےجس کے سامنے سب فلسفے اورمذاہب اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے شیر کے سامنے سے لومڑ.فَسُبْحَانَ اللہِ الْمَلِکِ الْعَزِیْزِ.اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرادعویٰ ہے کہ اس مامور کی اتباع کی برکت سے کسی علم کامتبع خواہ قرآن کریم کے کسی مسئلہ پر حملہ کرے.میں اس کامعقول اورمدلّل جوا ب دے سکتاہوں اوراللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ذی علم کو ساکت کرسکتاہوں خواہ وقتی جوش کے ماتحت وہ علی الاعلان اقرار کرنے کے لئے تیار نہ ہومیں نے اس کاربع صدی سے زیادہ عرصہ میں تجربہ کیاہے.میں سمجھتاہوں کہ جب سے اس میدان میں داخل ہواہوںاللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہرو باطن میں کبھی مجھے اس بارہ میں شرمندہ ہونے کاموقعہ نہیں ملا.قرآن مجید کی معنوی حفاظت غرض خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی معنوی حفاظت کامدار صرف عقل پر ہی نہیں رکھا اوراس کی تشریح کاانحصار صرف انسانی دماغ پر ہی نہیں چھوڑابلکہ خوداپنے کلام سے اس کو ظاہرفرمانے کاذمہ لیاہے جس کاایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب اس طرح سے عملی پھل ظاہرہوتے ہیں توقرآن مجید کے محفوظ ہونے کاایک بیّن ثبوت ملتارہتاہے.دوائی اگرفائدہ کرتی ہے تو ہم اسے تازہ سمجھتے ہیںورنہ بوسیدہ سمجھتے ہیں.قرآن مجید کے تازہ پھل بھی ثابت کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید محفوظ اورزندہ کتاب ہے اوریہ قرآن مجید کی حفاظت کاایسازبردست
Page 227
ذریعہ ہے جواور کسی کتا ب کو میسر نہیں اورنہ کبھی ہوگا.قرآن مجید کا نام ذکر رکھے جانے کی وجہ جیساکہ بتایاجاچکاہے.ذِکرکے معنے شرف اورنصیحت کے بھی ہیں قرآن کریم کانام ذکر اس لئے رکھا گیاکہ اس کے ذریعہ سے اس کے ماننے والوں کو شرف اورتقوی حاصل ہوگا.پس اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کلام جس کایہ دعویٰ ہے کہ میرے ذریعہ سے ماننے والوںکو شرف اورعزت اورتقویٰ ملے گا.ہماراہی اُتاراہواہے اورہم ہی اس کے محافظ ہیں یعنی ان صفات کو عملاً پوراکرناہماراہی کام ہے.اگریہ صفات اس کی ظاہر نہ ہوں توگویا اس کی تعلیم ضائع گئی مگرہم ایسانہیں ہونے دیں گے.اس آیت میں کفار کی تباہی اورمسلمانوں کے غلبہ کی بھی پیشگوئی ہے کیونکہ قرآن کریم ہرقسم کی سیاسی،اقتصادی اورنظامی تعلیمات کامجموعہ ہے اورشرعی کلام جب تک اپنے ابتدائی ایام میںایک حکومت کے ساتھ متعلق نہ ہو اس کی تعلیم کے عملی حصہ کی خوبیاں پوری طرح ظاہر نہیں ہوسکتیں.پس الذکر کی حفاظت کے لئے ایک حاکم قوم کی ضرورت تھی او ر ایسی قوم کے قیام سے پہلے عرب کی موجودالوقت حکومت کی تباہی لازمی تھی.لوگ اسلامی حکومت کے قیام کو ایک اتفاق کہہ دیا کرتے ہیں.اول تومحض اسلامی حکومت کاقیام بھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن میں وہ قائم ہوئی کسی صورت میں اتفاق نہیں کہلاسکتالیکن اس پیشگوئی کو دیکھتے ہوئے توکوئی انسان جس میں ذرابھر بھی عقل ہو اسے اتفاق نہیں کہہ سکتا.قرآن یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ عربوں کی حکومت ٹوٹ کر ان کی جگہ مسلمانوں کی حکومت ہوجائے گی.قرآن یہ کہتاہےکہ یہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی (۱)جوخداترس ہوں گے.(۲)جودنیا کی نگاہ میں اعلیٰ شرف والے قرار پائیں گے.اس میں کوئی شک نہیں کہ ہزاروں حکومتیں ٹوٹتی ہیں اوردوسری ان کی جگہ لیتی ہیں مگر کیا ہر حکومت کے ٹوٹنے کے بعد جودوسری حکومت جگہ لیتی ہے وہ انہی صفات کی حامل ہوتی ہے جن کااوپر ذکر ہواہے؟مگر اس پیشگوئی کے نتیجہ میں عرب کی حکومت ٹوٹ کر کیسی حکومت قائم ہوئی ؟ شدید سے شدید دشمن بھی جو اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو گالیاں دیتاہے جب ابوبکرؓ اورعمرؓ تک پہنچتاہے توعزت سے گردن جھکالیتا ہے اوران کے تقویٰ اورعقل اورفہم اورنیک انتظام اور ایثار اور قربانی کا اعتراف کرتاہے.اس قسم کی حکومت کاقائم ہوجانابھی کیااتفاق کہلاسکتاہے خصوصاً جبکہ وہ پیشگوئی کے ماتحت تھی اورقرآن کریم میں صاف کہہ دیاگیاتھاکہ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَیْکُمْ کِتَابًا فِیْہِ ذِکْرُکُمْ اَفَلَاتَعْقِلُوْنَ (الانبیاء :۱۱) ہم نے یقیناً تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے
Page 228
جس میں تمہارے شرف دینی اوردنیوی عزت کے سامان موجود ہیں پھر تم کیوں مخالفت سے باز نہیں آتے ؟ لفظ ذکر میں مسلمانوں کی ترقی کی پیشگوئی اسی صفت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لئے قرآن کریم کانام بعض دفعہ اَلذِّکْر آتا ہے اورآیت زیرتفسیر میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیاہے کہ اے کفار !تم طنز سے کہتے ہو کہ اے وہ شخص! جس پر وہ کلام نازل ہواہے جس میں ماننے والوں کے لئے بڑی عزت اورتقویٰ کادعویٰ کیاگیاہے توپاگل ہے.مگرمَیں تم کو بتاتاہوں کہ یہ کلام میراہی نازل کیاہواہے اور میں اس شرف کے وعدہ کو ضرورپوراکرکے رہوں گا کیونکہ یہ شرعی کلام ہےاوربغیر اس کے کہ ابتدائی زمانہ میں اس کے ماننے والوں کو حکومت ملے اوردینی رتبہ کے ساتھ دنیوی رتبہ بھی حاصل ہو.یہ کلام عملی جامہ نہیں پہن سکتااورغیرمحفوظ ہو جاتاہے پس ضرور ہے کہ میں موجود ہ نظام کو توڑ کر وہ نظام قائم کروں جس میں مسلمانوں کو قرآنی تعلیم کو عملی جامہ پہنانے کاموقعہ ملے اوران کو ایسے شرف اور تقویٰ کے اظہار کاموقعہ ملے جس کاوعدہ قرآن میں کیاگیاہے.یہ مضمون اس آیت کو وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ (الحجر :۵)والی آیت کے ساتھ ملاکر دیکھنے سے اوربھی واضح ہو جاتا ہے.ہر نبی کے کلام کی حفاظت کئے جانے کے متعلق ایک سوال کا حل ایک سوال کاحل اس موقعہ پر ضروری ہے میں نے ا س نوٹ کے سلسلہ میں بیان کیاہے کہ ہرنبی کے کلام کی حفاظت کی جاتی ہے.اگلی آیات اس مضمون کی تصدیق کرتی ہیںاوریہ قانون ہرنبی کے متعلق ہے اب سوال یہ ہے کہ اگریہ درست ہے توکیا (۱)پہلے انبیاء کی وحی اب تک بعینہٖ محفوظ ہے ؟ (۲)اگرنہیں توپھر یہ کیونکر تسلیم کیاجائے کہ قرآن کریم ہمیشہ محفوظ رہے گا.کیوں نہ تسلیم کیاجائے کہ یہ بھی پہلے انبیاء کی وحیوں کی طرح کسی وقت بگڑ جائے گا.اس سوال کا جواب خود آیت زیر تفسیر کے الفاظ ہی دے رہے ہیں قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے یاکتاب کی حفاظت کریں گے بلکہ الذکر کی حفاظت کاوعدہ کیاہے.جب تک کوئی کلام الذِّكْرُ رہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اس لفظ کو استعمال کرکے حفاظت کے دائرہ کو محدود کردیاگیاہےجب تک کو ئی کلام الذکر رہے یعنے (۱) ایک طرف تو بندہ اورخدا تعالیٰ کے تعلق کو قائم کرتارہے (ذکر کے معنے یاد کرنے کے ہیں )اوربندہ کوایسے قیام پر کھڑارکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سرشار رہے اور(۲)دوسری طرف اسے ایسامقام عطاکرے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد کرتارہے یعنے خدا تعالیٰ کی وحی اورنصرت اورامداد بندہ کو حاصل رہے اس کی حفاظت کااللہ تعالیٰ ذمہ لیتا ہے جو کلام ان خوبیوں کاحامل رہے گا.خدتعالیٰ اس کی حفاظت کر ےگااورجوکلام ان خوبیوںکاحامل نہ ہوگااللہ تعالیٰ اس کی حفاظت چھوڑ دے گا.
Page 229
یہ امر ظاہر ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کلام کو دنیا کے لئے قابل عمل سمجھے گا.اس میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی او ر جب اللہ تعالیٰ کسی کلام کو ضرور ت زمانہ کے پوراکرنے سے قاصر قرار دےدے گااور اس کی حفاظت چھوڑ دے گاتاکہ نئے سرے سے ایساکلام نازل کرے.جو ضرورت زمانہ کے مطابق ہو تو مذکورہ بالا امور اس نئے کلام کے ذریعہ سے پورے ہونے لگیں گے اورسابق کلام سے پورے نہ ہوں گے اورجب وہ ضرورت جس کے لئے کلام الٰہی نازل ہوتاہے.پوری نہ ہوگی.تو اس کی حفاظت کی بھی ضرورت نہ رہے گی.اورجب اللہ تعالیٰ کی حفاظت اُٹھ جائے گی تو شرارتی لوگوں کو اس کلام میں دخل دینے کا او ر تحریف کرنے کا موقعہ بھی ملتارہے گا.ہر نبی کی وحی جب تک الذکر رہی اس کی حفاظت ہوتی رہی خلاصہ کلام یہ کہ باوجود اللہ تعالیٰ کے وعد ہ کے کہ و ہ ہر نبی کی وحی کی حفاظت کرے گا.پہلے انبیاء کی وحی اگر محفوظ نہیں رہی.توقابل اعتراض نہیں.کیونکہ قرآن نے الذکر کی شرط لگائی ہے.جب تک وہ الذکر رہے.ان کی حفاظت ہوتی رہی.جب وہ الذکر نہ رہے ان کی حفاظت کاوعدہ ختم ہوگیا.اوریہ کہ وہ الذکر نہ رہے.ایک بدیہی بات ہے.کم سے کم اپنے زمانہ میں ہم میں سے ہر اک اس کاتجربہ کرسکتاہے.آج کل سوائے اسلام کے ایک مذہب بھی نہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کے پیروئوں میں کو ئی ایسا شخص موجود ہے.جو الذکر کا عملی ثبوت ہو یعنے اس کایہ دعویٰ ہوکہ اپنے مذہب کی کتاب پر چل کر اسے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگیاہے.اورخدا تعالیٰ اسے یاد کرتاہے یعنے اس سے کلام کرتاہے ا ور اس کے لئے اپنی قدرتوں کو ظاہر کرتاہے.جو الذکر کا مفہوم ہے.پس جب عملاًوہ کتب الذکر کا مصدق نہیں رہیں.تو ان کی حفاظت بھی جاتی رہی اور ان کے محرّف و مبدّل ہونے میں کوئی آسمانی روک نہیں.قرآن مجید اب تک ذکر ہے باقی رہاسوال کایہ حصہ کہ پھر کیوں قرآن کریم کی نسبت بھی یہ نہ تسلیم کیاجائے کہ وہ بھی حفاظت سے باہر ہوگیا ہے.تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اب تک الذکر ہے.اس پر چل کر آج بھی انسان خدا تعالیٰ کو پاسکتاہے.پس چونکہ وہ اس ضرورت کو پورا کررہاہے جس کے لئے اسے نازل کیاگیاتھاوہ خدا تعالیٰ کی حفاظت سے باہرنہیں ہوسکتااور کسی کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس کے اند رکوئی تغیّر و تبدّل کرے.اب رہا سوال آئندہ کاسو اس کااول تویہ جواب ہے کہ اس وقت تک اس میں کوئی تغیر نہیں ہوااورآئندہ کے لئے قرآن کریم میں پیشگوئیاں موجود ہیں کہ جب بھی مسلمان اسلام سے غافل ہوں گے اللہ تعالیٰ مامور بھیجتا رہے گا.پس اس وعد ہ کی موجودگی میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم سے ہمیشہ دنیا کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی وہ نسخ کو قبول نہیں کرے گااور جب وہ نسخ کو قبول نہیں کرے گاتویقیناً وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے
Page 230
گا کیونکہ کوئی عقلمند اپنی کار آمد شے کو تباہ نہیں ہونے دیتا ا وراللہ تعالیٰ تو سب عقلمندوں سے بڑھ کر عقلمند ہے.وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ۰۰۱۱ اورہم نے اگلے (زمانہ کے ) لوگوں کی جماعتوں میں (بھی ) تجھ سے پہلے رسول بھیجے تھے.حلّ لُغَات.شِیَعٌ.شِیَعٌ شِیْعَۃٌ کی جمع ہے.شِیْعَۃُ الرَّجُلِ.اَتْبَاعُہُ واَنْصَارُہُ شِیْعَۃُ الرَّجُلِ کے معنے ہیں.آدمی کے اتباع اور مددگار (اقرب) شِیَعِ الْاَ وَّلِیْنَ کے متعلق فراء نے کہا ہے کہ یہ اِضَافَۃُ الشَّیءِ اِلٰی صِفَتِہِ کی طرز پر ہے.یعنی اس کے معنے ہیں پہلے جتھے.(بحر محیط) تفسیر.اللہ تعالیٰ نے تمام گروہوں کو شیعہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام گروہوں کو شیعہ کہا ہے.اس سے ان لوگوں کی تردید ہوتی جو کہاکرتے ہیں کہ ہم ہرطرح سے آزاد ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں وہ نہ آزاد ہوتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں وہ یہ فقرہ صرف چالاکی سے کہتے ہیں تاکہ وہ تو اعتراض کرتے چلے جائیں لیکن ان پر کوئی اعتراض نہ کرسکے.آزادی کا دعویٰ کرنا غلط ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ کوئی آزاد بھی ہوتاہے ہرآدمی کسی نہ کسی کے ماتحت یا کسی نہ کسی جتھے میں ضرور ہوتاہے.خواہ مذہب کی بنا پر ہو خواہ رسم کی بناء پرخواہ فلسفہ کی بناپر کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ آزاد ہو ہر انسان کو اپنی زندگی میں اتنے امور سے واسطہ پڑتا ہے کہ ہر امر کی بابت تحقیق کرنا اس کے لئے ناممکن ہوتاہے.اس لئے کچھ نہ کچھ امور میں وہ ایسے لوگوں کے خیالات کو قبول کرلیتا ہے جن پر اسے اعتقاد ہوتاہے.شیع الاولین سے انسان کے نقل کرنے کی طرف اشارہ سائیکالوجی والے(علم النفس کے ماہرین) کہتے ہیں کہ انسان میں نقل کرنے کامادہ اس کاسب سے بڑاخاصہ ہے.اسی بات کو اس جگہ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ کہہ کر بیان کیا گیاہے یعنے مختلف جتھے جو کسی نہ کسی سبب سے آپس میں متحد تھے.اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کے متعلق یہ بتایاگیا ہے کہ پہلے بھی نبی گزرے ہیں اور ان کی تعلیم کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے اسی طرح اس رسول کی تعلیم کی بھی حفاظت کرے گاحفاظت سے مراد جیساکہ بتایاجاچکاہے نہ صرف لفظی حفاظت ہے بلکہ معنوی حفاظت بھی ہے جوشرعی نبیوں کے
Page 231
زمانہ میں علاوہ اورذرائع کے اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ان کے زمانہ میں ہی حکومت ان کی جماعت کو مل جاتی ہے اور وہ عملاً اس شریعت کو رائج کرکے اس کے اصلی معنوں کو ظاہر کرجاتے ہیں اورجو شرعی نبی نہ ہوں.ان کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ غلبہ دیتاہے تاکہ ان کی تعلیم کے عملی ثمرات ظاہر ہوں لیکن ان کے لئے فوری حکومت کاملنا ضروری نہیں.غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کلام الٰہی کی حفاظت کاسلسلہ ہمیشہ سے چلاآتاہے اسی رنگ میں تم اب نشان دیکھ لو گے.نہایت تعجب کی بات ہے کہ انبیاء کے منکرین اس سہل ترین راستہ کو قبول کرنے سے ہمیشہ پہلو تہی کرتے ہیں جو انہیں یقینی طور پر سچے نبی کی شناخت میں ممد ہوسکتا ہے اوروہ راستہ منہاج نبوت کے مطابق مدعی کے دعویٰ کو پرکھنا ہے.اگرمنہاج نبوت کے مطابق مدعی کے دعویٰ کو پرکھا جائے تواس کی صداقت یا اس کے کذب کو معلوم کرنا ایک ساعت کاکام ہوتاہےمگر اسی راستہ کو قبول کرنے سے وہ پہلو تہی کرتے ہیں.جس سے معلوم ہوتاہے کہ صداقت کو معلوم کرنا مطلوب نہیں ہوتابلکہ خلط مبحث کرکے سچائی سے گریز کرنا مطلوب ہوتاہے.وَ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۠۰۰۱۲ اور جو رسول بھی ان کے پاس آتاتھاوہ اس کی ہنسی اُڑاتے تھے.تفسیر.اِسْتِھْزَاءٌ اس ہنسی کوکہتے ہیں جس میں تحقیر پائی جائے.اس آیت کاتعلق ایک تو يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ سے ہے کہ اس میں کفار کے تمسخر کی طرف اشارہ کیاگیاہے.کفار کا انبیاء سے تمسخر فرماتا ہے اس نبی سے تم نے تمسخرکرلیا توکیاہواوہ انبیاء جن کو تم مانتے ہوان سے بھی تو تمسخر ہوتارہاہے.دوسرے یہ بتایا کہ ہرنبی کے کلام اوراس کی تعلیم کی حفاظت کاوعدہ ہوتاہے اوریہ امر کفار کو عجیب معلوم ہوتاہے کہ ہماری مخالفت کے باوجود یہ تعلیم کس طرح باقی رہ جائے گی اور و ہ اس دعویٰ کوغیر معقول سمجھ کر اس سے ہنسی کرتے رہے ہیں.تعجب ہے کہ ہرنبی سے تمسخر ہواہے پھر بھی جب کوئی نیانبی آتاہے دنیا اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ کیوں اسے خاص شان نہیں ملی.اگر خاص شان اورطاقت سے نبی آتے توگزشتہ نبیوںسے تمسخر کیونکر ہوسکتاتھا؟
Page 232
كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَۙ۰۰۱۳ اسی طرح ہم اس (عادت استھزاء)کو مجرموں کے دلوں میںداخل کرتے ہیں.حلّ لُغَات.نَسْلُکُہٗ.نَسْلُکُ سَلَکَ سے مضارع جمع متکلم کاصیغہ ہے.اورسَلَکَ الْمَکَانَ سَلْکًا وَسُلُوْکاً کے معنی ہیں دَخَل فِیْہِ کسی جگہ میں داخل ہوااوراس کے اندر گیا سَلَکَ الطَّرِیْقَ اَیْ دَخَلَہٗ وَسَارَفِیْہِ مُتَّبِعًااِیَّاہُ.فَھُوَسَالِکٌ.اورسَلَکَ الطَّرِیْقَ کے معنی ہیں.راستہ اختیار کرکے اس پر چل پڑااوراس سے اسم فاعل سَالِک (یعنی راستہ اختیار کرکے اس پر چلنے والا)آتاہے.سَلَکَ الشَّیْءَ فِی الشَّیْءِ.اَدْخَلَہٗ فِیْہِ کَمَا تُسْلَکُ الْیَدُ فِی الْجَیْبِ وَالْخَیْطُ فِی الْاِبْرَۃِ.اور سَلَکَ الشَّیْءَ فِی الشَّیْءِ کے معنی ہیں.ایک چیز کو دوسری چیز کے اندرداخل کیا جیسے گریبان میں ہاتھ ڈالنا یاسوئی کے سوراخ میں تاگہ ڈالنا.وفی القرآن سَلَکْنٰہٗ فِی قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ.اورقرآن مجید کی آیت سَلَکْنَاہُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَمیں یہ لفظ انہی معنوں میں آیاہے.وَسَلَکَ فُلَانًاالْمَکَانْ کے معنے ہیں اَدْخَلَہٗ.فلاں شخص کو مکان میں داخل کیا.(اقرب) المجرمین اَلْمُجْرِمِیْنَ(جَرَمَ.یَجْرِمُ.جَرمًا)جَرَمَہٗکے معنی ہیں.قَطَعَہٗ.کاٹا.وَمِنْہُ جَرَمَ النَّخْلَ جَرْمًا اِذَاصَرَمَہٗ کھجور کو کاٹ کر جداکردیا.جَرَ مَ زیدٌ.اَذْنَبَ.زید نے جرم کاارتکاب کیا.جَرَمَ عَلٰی قَوْمِہٖ وَالٰی قَوْمِہٖ جَرِیْمَۃً جَنَی.جِنَایَۃً قو م پر زیادتی کی.وَجَرَمَ لِاَھْلِہٖ.کَسَبَ.کمایا.وَمِنْہُ فِی الْقُرْاٰنِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا.اَیْ لَا یَکْسِبَنَّکُمْ وفُسِّرَ اَیْضًا بِلَا یَحْمِلَنَّکُمْ.اورقرآن مجید کی آیت لَایَجْرِمَنَّکُمْ میں جرمَ کے معنے کمانے کے کئے گئے ہیں.یعنے دشمن کی دشمنی تمہارے لئے اس امر کی محرک نہ ہوکہ تم ظلم کمائو.اس کے علاوہ اس سے یہ بھی مراد لی گئی ہے.کہ لَایَحْمِلَنَّکُمْ یعنی تم کو آمادہ نہ کرے.اَجْرَمَ.اَذْنَبَ.عَظُمَ جُرمُہ.اجْرَمَ کے معنے ہیں.قصورکیااوراس کاقصوربڑا تھا.اَجرَمَ عَلَیْھِمْ جَنَی ظلم کیا.(اقرب) ان تمام محاورات سے ظاہر ہے کہ اصل میں جرم کے معنے قطع کے ہوتے ہیں.گناہ چونکہ خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرواتاہے اوربنی نوع انسان سے بھی.اس لئے اسلامی شریعت میں گناہ کو جرم کہاجاتاہے اورگناہ وہی ہوتا ہے.جس سے یا خدا سے تعلق ٹوٹے یابندوں سے بگاڑ پیداہو.پس اَلْمُجْرِمُ کے معنے ہونگے صَارَاذَاجُرمٍ یعنی تعلق کو کاٹنے والا.تفسیر.نَسْلُکُہُ کی ضمیر کے مرجع کے متعلق اختلاف اس آیت میں نَسْلُکُہ کی ضمیر کے
Page 233
مرجع کے متعلق مفسرین میں اختلاف ہواہے بعض نے اسے لَایُؤْمِنُوْنَ کی طرف بطو ر ضمیر مقدم کے راجع کیا ہے اوربعض اس کو پہلی آیت کی طرف لے گئے ہیں(مجمع البیان زیر آیت ھذا).مگرمیرے نزدیک اس کامرجع استھزاء ہے.جوپہلی آیت میں مذکور ہواہے.نَسْلُكُهٗ کی ضمیر کا مرجع استہزاءہے كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ.کہہ کر اس بات کو ظاہر کیاہے کہ جب انسان برے فعل کا ارتکاب کرتاہے تو صرف اس گناہ کامرتکب نہیں ہوتا.بلکہ گناہ کی نفرت بھی اس کے دل سے کم ہوجاتی ہے اورآہستہ آہستہ اس کے دل میں گناہ کی محبت پیداہوجاتی ہے اورگناہ اس کے دل میں گھر بنالیتا ہے.اللہ تعالیٰ گناہ کے طبعی نتائج نکالتا ہے اس آیت سے ثابت ہوتاہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گنہگار نہیں بناتا.بلکہ گناہ کے طبعی نتائج نکالتاہے.اوراس کا الزام اللہ تعالیٰ پر نہیں بلکہ خود گنہگار پر آتاہے.لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ۰۰۱۴ یہ (لو گ) اس پر ایمان نہیں لاتے.حالانکہ پہلوں(کے متعلق اللہ تعالیٰ)کی سنت گز رچکی ہے.حلّ لُغَات.اَلسُّنَّۃُ.اَلسُّنَّۃُ السِّیْرَۃُ سنت کے معنی ہیں دستور.الطَّرِیْقَۃُ.طریقہ.اَلطَّبِیعَۃُ.طبیعت عادت.(اقرب) تفسیر.استہزاء سے دل سخت ہو جاتے ہیں یعنے استہزاء کی جب عادت ہوجاتی ہے تودل سخت ہوجاتے ہیں اورآخر باوجود کھلے نشانات دیکھنے اور واضح ثبوت موجود ہونے کے لوگ ایمان سے محروم ہوجاتے ہیں یہی حال پہلی قوموں کاہوا.یہی ان کاہوگا.استہزاء کرکے کس نے ہدایت پائی کہ اب یہ پائیں گے.وَ لَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ اوراگر( بالفرض)ہم ان پر (شناخت کی)کو ئی آسمانی راہ کھول (بھی )دیتے.اوروہ اس میں چڑھنے لگتے يَعْرُجُوْنَۙ۰۰۱۵لَقَالُوْۤا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ (اورقرآن مجید کامنجانب اللہ ہونا ان پر ظاہر ہوجاتا)تو(بھی)وہ (یہی ) کہتے (کہ)محض ہماری نظروں پر پردہ
Page 234
قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَؒ۰۰۱۶ ڈالاگیاہے (ورنہ حقیقت کچھ بھی نہیں) بلکہ ہم (لوگوں)پر (کو ئی)جادوکردیاگیاہے.حلّ لُغَات.یَعْرُجُوْنَ.یَعْرُجُوْنَ عَرَجَ یَعْرُجُ عُرُوْجًا سے مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے.اورعَرَجَ الرَّجُلُ فی الدَّرَجَۃِ وَالسُّلَّمِ کے معنی ہیں.اِرْتَقٰی.آدمی سیڑھی پر چڑھا.وعُرِجَ بِہٖ عَلٰی الْمَجْہُوْلِ.صُعِدَ بِہٖ.اورمجہول ہو تو اس کے معنے ہیں.اس کو چڑھاکر لے جایاگیا.(اقرب) سُکِّرتْ.سُکِّرَتْ سَکَرَ (یَکْسُرُ سَکْرًا)الْاِنَائَ کے معنے ہیں.مَلَأَ ہٗ.برتن کو بھر دیا.سَکَرَتِ الرِّیْحُ.سَکَنَتْ بَعْدَ الھَبُوْبِ ہواچلنے کے بعد تھم گئی.سَکَرَتْ عَیْنُہُ.تَحیَّرَتْ وَ سَکَنَتْ عَنِ النَّظَرِ.آنکھ حیران ہوگئی اوردیکھنے سے رک گئی.سَکَرَ البَابَ.سَدَّہٗ.دروازہ بند کردیا.سُکِرَت اَبْصَارُنا مَجْہُوْلًا حُبِسَتْ.آنکھیں روکی گئیں.سُکِّرَت اَبصَارُنَا مَجْھُوْلًا.حُبِسَتْ وحُیِّرَتْ.آنکھیں حیران کردی گئیں اورروکی گئیں.(اقرب) اَبْصَارُنَا.اَبْصَارُنَا اَبْصَارٌ.بَصَرٌ کی جمع ہے.اور اَلْبَصَرُ کے معنی ہیں.حَاسَّۃُ الرُّؤیَۃِ.دیکھنے کی حس.اَلْعَیْنُ آنکھ.اَلْعِلْمُ علم.(اقرب) مَسْحُورون.سَحَرَ.یَسْحَرُ.سِحْرًا کے معنے ہیں.عَمِلَ لَہُ السِّحْرَ وخَدَ عہٗ.اس پر سحر کیا او ر اسے دھوکا دیا.سَحَرَ عَنْہُ.تَبَاعَدَ.دورہوگیا.سَحَرَ فُلَانًا عَنِ الْاَمْرِ صَرَفَہَ.کام سے روک دیا.سَحَرَ بِکَلَامِہٖ وَالْحَاظِہٖ.اِسْتَمَالَہُ وَسَلَبَ لُبَّہُ.اپنے کلام اورنظروں سے مائل کرلیا اورعقل کو چھین لیا.سَحَرَ الْمَطَرُ الطِّیْنَ وَالتُّرَابَ سَحْرًا اَفْسَدَہُ فَلَمْ یَصْلَحْ لِلْعَمَلِ.بارش نے مٹی اورکیچڑ کو خراب کردیااوروہ کام کے قابل نہ رہی.اَلْمَسْحُوْرُاَیْضًاالْمُفْسَدُ مِنَ الطَّعَامِ وَالْمَکَانِ لِکَثْرَۃِ الْمَطَرِ اَوْمِنْ قِلّۃَ الکَلَاءِ.مسحورکے ایک معنے بر ے کھانے کے ہیں اورایسی جگہ پر بھی مسحور کالفظ بولتے ہیں جوکثرت بارش یا گھاس کی کمی کی وجہ سے خراب ہوجاوے.(اقرب) تفسیر.کفار کی طرف سے فرشتوں کے دکھانے کے مطالبے پر دو جواب لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰٓىِٕكَةِ کی آیت میں کفار کی طرف سے مطالبہ بیان ہواتھا کہ اگر اس کادماغ (نعوذباللہ)خراب نہیں اوراسے وہم نہیں توجو فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھاتا.
Page 235
پہلا جواب اس کا جواب ایک تویہ دیاتھاکہ فرشتے ہرایک کے مناسب حال نازل ہوتے ہیں.یہ توعذاب کے مستحق ہیں.عذاب ہی کے فرشتے ان پر نازل ہوں گےمگر ان کے نزول سے یہ ہلاک ہونے کے بعد کیافائدہ اُٹھائیں گے.دوسرا جواب دوسراجواب یہ دیاکہ تم فرشتوں کاکہتے ہواوران کے نزول پرتعجب کرتے ہو.ہم تواس پر نازل ہونے والے کلام کی خود حفاظت کریں گے کیونکہ وہ ہماراکلام ہے اوراس کی حفاظت کی ذمہ واری سب سے زیادہ ہم پر پڑتی ہے.آخر ہم پہلے نبیوں کے زمانہ میں بھی یہ کام کرتے آئے ہیں.اب کیوں نہ کریں گے پھر فرمایاتھاکہ یہ استہزاء ان کا تعجب انگیز نہیں کہ سب نبیوں کے دشمنوں نے ان سے استہزاء کیا اوراس قد ر استہزاء کیاکہ آخر گناہ ان کی غذاہوگیااوراس میں ان کو لذت آنے لگی اوروہ ایمان سے محروم ہوگئے یہی ان کا حال ہے.کفار کے مطالبہ کا ایک اور طریق پر جواب اب ایک او رطریق پر انہیں جواب دیتاہے.فرماتا ہے کہ تم جو کہتے ہوکہ فرشتے ہمیں کیوں نہیں دکھاتاآپ ہی گھر میں بیٹھا دیکھ لیتا ہے.تم یہ بتائوکہ کیا ہربات کو ہرشخص سمجھنے کی قابلیت رکھتاہے.جب تک دل میں اس سے مناسبت نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آسکتی.تم کو توالٰہی علوم سے اس قدر بُعد ہے کہ اگراسی قسم کے نظارے تم کو نظر آنے لگیںجومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے ہیں اور تم کو روحانی مدارج کی سیر بھی کرائی جائے توتم کبھی نہ مانوگے بلکہ یہی کہو گے کہ ہماری آنکھوں پر جادوکردیاگیاہے ہمیں عجیب عجیب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں کیونکہ تمہارے قلوب میں روحانی علوم سے کوئی لگائو نہیں.آسمانی دروازہ کھلنے اور اوپر چڑھنے سے مراد گویاآسمانی دروازہ کے کھلنے سے مراد اس جگہ آسمانی انکشاف ہے اوراوپر چڑھنے سے مراد بعض روحانی مدارج کاکھلنا ہے.بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ سے ایک اور نمونہ دکھائے جانے کی طرف اشارہ ہے اگرکہا جائے کہ جس پرآسمانی دروازہ کھولاگیا وہ ایمان سے کس طرح محروم رہ سکتاہے.اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ کہاگیاہے یعنے کوئی دروازہ جس سے اس طرف اشارہ کیاگیاہے کہ وہ کلی طور پر آسمانی علوم سے آشنا نہ کیاجائے اورہرقسم کی معرفت کی راہیں اس کے لئے نہ کھولی جائیں بلکہ بوجہ اس کے انکار کے اسے ایک نمونہ دکھایاجائے اوریہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جب تک دل میں مناسبت پیدانہ ہوجائے انسان محض نمونہ دیکھ کر فائدہ نہیں اٹھاتا اور وہ نظارہ صرف حجت پوری کرنے کے کام آتاہے.ایمان کاموجب نہیں بنتا.کفار کی عادت یہ ایک تجربہ شدہ امر ہے کہ کئی لوگ مامورین کاانکارکرتے ہیں اوریہ مطالبہ کرتے ہیںکہ اگر
Page 236
کوئی نشان نظر آجائے توپھر مانیں گے لیکن جب نشان نظرآجائے توپھر کبھی توکوئی بہانہ بنالیتے ہیں.کبھی تعبیر غلط کرلیتے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ خواب الہام کیا شے ہے یونہی وہم ہے.غرض نشان دیکھ کر بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اوراس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل میں خشیت اللہ نہیں ہوتی ا س لئے نشان سے فائدہ نہیں اٹھاسکتے.اسی حالت کی طرف اس آیت میںا شارہ کیاگیاہے کہ ماننے کے لئے پہلے دل کی حالت کی درستی ضروری ہے.خشیت اللہ ہوتو پھر ایمان نصیب ہوتاہے ورنہ ایک چھوڑ سو فرشتے نظرآئیں انسان اپنے دل کی تسلی کے لئے کئی بہانے بنالیتا ہے اورایمان لانے سے انکار کردیتاہے.اس آیت کے یہ بھی معنے ہوسکتے ہیں کہ ان پر عذاب آتے ہیں.عذاب کو دیکھ کر ان میں خشیت پیداہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم مان لیں گے جیساکہ فرعون کے ذکر میں قرآن کریم میں آتاہے.ان معنوں کی روسے فَتَحنَا باباً من السماء کے معنے رحمت کے دروازے کاکھولنا اورعذاب کا ٹلادینا ہوگا.اور ظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَسے مراد آرام کی ساعتوں میں دنیوی ترقیات کے حاصل کرنے میں مشغول ہوجاناہوگا.عذاب کا ذکر پہلےمَا كَانُوْۤااِذًا مُّنْظَرِيْنَ میں آچکا ہے.مطلب یہ ہے کہ تم لوگ توایسے سنگدل ہوکہ عذاب آنے پر ندامت کااظہار کروگے اورپھرمنکرہو جایاکروگے.وَ لَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَۙ۰۰۱۷ اوریقیناً ہم نے آسمان میں (ستاروں کی ) کئی منزلیں بنائی ہیں اورہم نے اسے دیکھنے والوں کیلئے (ستاروں کے وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍۙ۰۰۱۸ ذریعہ سے)خوبصورت بنایاہے.اور(نیز) ہم نے اسے ہرایک سرکش (اور)دھتکارے ہوئے (کی رسائی) سے محفوظ کردیاہے.حلّ لُغَات.السَّمَآءُ کے معنے ہیں آسمان مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت نمبر ۴.السَّمٰوٰت.سَمَاءٌ کی جمع ہے.السَّمَاءُ.آسمان.کُلُّ مَاعَلَاکَ فَاظَلَّکَ.ہر اوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز.سَقْفُ کُلِّ شَیْءٍ وَبَیْتٍ چھت رُوَاقُ الْبَیْتِ برآمدہ.ظَھْرُالْفَرَسِ گھوڑے کی پیٹھ.اَلسَّحَابُ.بادل.اَلْمَطَرُ بارش.اَلْمَطَرَۃُ الْجَیِّدَۃُ ایک دفعہ کی برسی ہوئی عمدہ بارش.اَلْعُشْبُ سبزہ و گیاہ.(اقرب)
Page 237
بُرُوْجًا.بُرُوْجًا بُرُوْجٌ کامفرد بُرْجٌ ہے.اوراَلْبُرْجُ کے معنے ہیں.الرُّکْنُ وَالْحِصْنُ.مضبوط سہارا.پناہ گاہ.قلعہ.اَلْقَصْرُ.محل.وَاحِدُ بُرُوْجِ السَّمَائِ آسمان کے برجوں میں سے ایک برج یعنی ستاروں کے چکر لگانے کی منزل.بُرْجٌ کی جمع بُرُوْجٌ کے علاوہ اَبرَاجٌ اوراَبْرِجَۃ بھی آتی ہے.(اقرب) البروج.القُصُوْرُ.محلات.منازل.وَبِہِ سُمِّیَ بُرُوجُ النُّجُوْمِ لِمَنَازِلھَا الْمُخْتَصَّۃِ بِھا.اور ستاروں کی منازل کو بھی برو ج کہاجاتاہے.(مفردات) لِلنَّاظِرِیَنَ.نَظَرَسے اسم فاعل نَاظِرٌ آتاہے اوراس کی جمع نَاظِرُوْنَ آتی ہے.نَظَرَ اِلَیْہِ نَظْرًاکے معنے ہیں اَبْصَرَہٗ.کسی چیز کو دیکھا.وتَأَمَّلَہ بِعَیْنِہِ کسی چیز کو آنکھ سے خوب غور سے دیکھا.مَدَّ طَرَ فَہُ اِلَیْہِ رَاٰہُ اَوْلَمْ یَرَہُ.کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھائی خواہ چیز کو دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے.ونَظَرَتِ الْاَرْضُ.اَرَتِ الْعَینَ نَبَا تَھَا.زمین نے اپنی سرسبزی آنکھ کو دکھائی.نَظَرَبَیْنَ النَّاسِ.حَکَمَ وَفَصَلَ دَعَاوِیَھُمْ لوگوں کے دعاوی کافیصلہ کیا.نَظَرَ فِی الْاَمْرِ نَظْرًا تَدَبَّرَہُ وَفَکَّرَ فِیْہِ یُقَدِّرُہُ وَیَقِیْسُہُ.کسی معاملہ کو کسی اورمعاملہ پر قیاس کرتے ہوئے اس پر غورکیا.(اقرب) شیطان کے معنے کے لئے دیکھو سورۃ یوسف آیت نمبر ۱۰۱.شَیْطٰنُ کا لفظ دو مختلف مادوں سے بن سکتا ہے.(۱) شَطَنَ.(۲) شَاطَ.یا تو یہ شَطَنَ سے فَیْعَالٌ کے وزن پر ہے اور شَطَنَ عَنْہُ کے معنے ہیں اَبْعَدَ دور ہو گیا.اور شَطَنَ الدَّارُ کے معنے ہیں گھر دور ہو گیا.پس اس مادہ کے لحاظ سے اس کے معنے ہوں گے کہ وہ ہستی جو حق سے خود بھی دور ہے اور دوسروں کو بھی دور کرنے والی ہے اور اگر شَاطَ اس کا مادہ مانا جائے تو اس کے معنے ہوں گے کہ وہ ہستی جو حسد اور تعصب کی وجہ سے جل جائے یا ہلاک ہو جائے.کیونکہ شَاطَ الشَّیْءُ کے معنے ہیں اِحْتَرَ قَ جل گئی اور شَاطَ فُلَانٌ کے معنی ہیں ھَلَکَ ہلاک ہو گیا.شَیْطٰنٌ اس سے فَعْلَانٌ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے.ان معنوں کے علاوہ شَیْطَنٌ کے معنے لغت میں مندرجہ ذیل لکھے ہیں.رُوْحٌ شَرِیْرٌ.بدروح.کُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ.سرکش اور حد سے بڑھنے والا.الـحَیَّۃُ سانپ.(اقرب) رَجیم.رَجِیْمٌ رَجَمَ میں سے ہے.اوررَجَمَہُ رَجْمًا کے معنے ہیں.رَمَاہُ بِالْحِجَارَۃِ.اس پر پتھر برسائے.قَتَلَہُ اس کو قتل کیا.قَذَفَہُ.اس پر تہمت لگائی.لَعَنَہٗ.لعنت کی.شَتَمَہُ.گالی دی.ھَجَرَہُ.چھوڑ دیا.ترک کردیا.اَلْقَبْرَ.علَّمَہُ.قبرپر نشان لگایا.جَاءَ یَرْجُمُ کے معنے ہیں.اِذَا مَرَّ وَھُوَ یَضْطَرِمُ فِیْ عَدْوِہٖ.تیزی سے دوڑتا ہوا گزرا.الرَّجُلُ.تَکلَّم بِالظَّنِ ظنی بات کی.(اقرب)
Page 238
الرَّجْمُ اَیْضاً اَنْ یَّتَکلَّمَ بِالظّنِ.رجم کے معنے غیر یقینی بات کرنے کے بھی ہیں جیسے آیت رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ میں رجم کے معنے ہیں.لَایُوْقَفُ عَلیٰ حقیْقَتِہٖ.یعنی بات کی حقیقت سے واقف نہ تھا.اِسْمُ مَایُرجَمُ بہٖ جس چیز سے ماراجائے اس کو بھی رجم کہتے ہیں.اس کی جمع رُجُوم آتی ہے.(اقرب) الرِّجَامُ.اَلْـحِجَارَۃُ.رجام کے معنے پتھروں کے ہیں.اورالرَّجْمُ کے معنے ہیں.الرَّمْیُ بِالرِّجَامِ کسی کو پتھر مارنا.جب کسی پر پتھرائو کیاجائے.تورُجِمَ بصیغہ مجہول استعمال کرتے ہیں.وَیُسْتَعَارُ الرَّجْمُ لِلرَّمِیِ بِالظَّنِّ.اوراِسْتِعَارَۃً رجم کالفظ خیالی اورغیر یقینی بات کے کرنے پر بھی بولاجاتاہے.وَالتَّوَھُّمِ وَلِلشَّتْمِ والطَّرْدِ.نیز یہ لفظ وہم سے بات کرنے.گالی دینے اوردھتکارنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتاہے.اور الشَّیْطَانُ الرَّجِیْمُ کے معنے ہیں.اَلْمَطْرُوْدُعَنِ الْخَیْراتِ.نیکیوں سے دور خوبیوں سے محروم و عاری.وَعَنْ مَنَازِلِ الْمَلَاءِ الْاِعْلیٰ فرشتوں کے مقامات سے دورکیاہوا(مفردات)اورمجمع البحارمیں ہے.وَرُجُوْمًا لِلشَّیَاطِیْنِ وَعَلَامَاتٍ ھُوَجَمْعُ رَجْمٍ مَصْدَرٌ سُـمِّیَ بِہٖ.رجم کالفظ مصدر ہے جو اسم کے طور پر استعمال ہواہے.اور رجوم اس کی جمع ہے.وَیَجُوْزُکَوْنُہُ مَصْدَرًا لَاجَمْعًا اوریہ بھی ہو سکتاہے.کہ رجوم مصدرہونہ کہ جمع.ومَعْنَاہُ اَنَّ الشُّھُبَ الَّتِیْ تَنْقَضُّ مُنْفَصِلَۃً مِنْ نَارِ الْکَوَاکِبِ ونُوْرِھَا لَااَنَّھُمْ یُرْجَمُوْنَ بِاَنْفُسِ الْکَواکِبِ لِاَ نّہا ثَابِتَۃٌ لَاتَزُوْلُ کَقَبَسٍ تُوْخَذُ مِنْ نَارٍ.یعنی وہ شہب جو ستاروں کی آگ سے علیحدہ ہوکر ٹوٹتے ہیں.وہ خود ستارے نہیں ہوتے.بلکہ ستاروں سے روشنی گرتی ہے کیونکہ ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں اورشہب کاگرنا اسی طرح ہوتاہے جیسے ایک چنگاری آگ سے لی جاتی ہے.وَقِیْلَ اَرَادَ بِالرُّجُوْمِ الظُّنُوْنَ الَّتِیْ تُحْزَرُومِنْہُ وَ یَقوْلُوْنَ خَمْسَۃٌسَادسُہُمْ کَلْبُہُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ.اوربعض محققین نے یہ کہاہے کہ رجوم سے مراد وہ خیالات ہیں جو اپنے قیاس سے بغیر دلیل کے انسان بنالیتا ہے اورانہی معنوں میں قرآن میں لفظ رجمًا بالغیب استعمال ہواہے.یعنی وہ غیب کے متعلق صرف اندازے لگاتے ہیں.(اس آیت کی تفسیر اگلی آیت کے ساتھ دیکھیں) الرَّجْمُ اَیْضاً اَنْ یَّتَکلَّمَ بِالظّنِ.رجم کے معنے غیر یقینی بات کرنے کے بھی ہیں جیسے آیت رَجْمًۢا بِالْغَيْبِ میں رجم کے معنے ہیں.لَایُوْقَفُ عَلیٰ حقیْقَتِہٖ.یعنی بات کی حقیقت سے واقف نہ تھا.اِسْمُ مَایُرجَمُ بہٖ جس چیز سے ماراجائے اس کو بھی رجم کہتے ہیں.اس کی جمع رُجُوم آتی ہے.(اقرب) الرِّجَامُ.اَلْـحِجَارَۃُ.رجام کے معنے پتھروں کے ہیں.اورالرَّجْمُ کے معنے ہیں.الرَّمْیُ بِالرِّجَامِ کسی کو پتھر مارنا.جب کسی پر پتھرائو کیاجائے.تورُجِمَ بصیغہ مجہول استعمال کرتے ہیں.وَیُسْتَعَارُ الرَّجْمُ لِلرَّمِیِ بِالظَّنِّ.اوراِسْتِعَارَۃً رجم کالفظ خیالی اورغیر یقینی بات کے کرنے پر بھی بولاجاتاہے.وَالتَّوَھُّمِ وَلِلشَّتْمِ والطَّرْدِ.نیز یہ لفظ وہم سے بات کرنے.گالی دینے اوردھتکارنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتاہے.اور الشَّیْطَانُ الرَّجِیْمُ کے معنے ہیں.اَلْمَطْرُوْدُعَنِ الْخَیْراتِ.نیکیوں سے دور خوبیوں سے محروم و عاری.وَعَنْ مَنَازِلِ الْمَلَاءِ الْاِعْلیٰ فرشتوں کے مقامات سے دورکیاہوا(مفردات)اورمجمع البحارمیں ہے.وَرُجُوْمًا لِلشَّیَاطِیْنِ وَعَلَامَاتٍ ھُوَجَمْعُ رَجْمٍ مَصْدَرٌ سُـمِّیَ بِہٖ.رجم کالفظ مصدر ہے جو اسم کے طور پر استعمال ہواہے.اور رجوم اس کی جمع ہے.وَیَجُوْزُکَوْنُہُ مَصْدَرًا لَاجَمْعًا اوریہ بھی ہو سکتاہے.کہ رجوم مصدرہونہ کہ جمع.ومَعْنَاہُ اَنَّ الشُّھُبَ الَّتِیْ تَنْقَضُّ مُنْفَصِلَۃً مِنْ نَارِ الْکَوَاکِبِ ونُوْرِھَا لَااَنَّھُمْ یُرْجَمُوْنَ بِاَنْفُسِ الْکَواکِبِ لِاَ نّہا ثَابِتَۃٌ لَاتَزُوْلُ کَقَبَسٍ تُوْخَذُ مِنْ نَارٍ.یعنی وہ شہب جو ستاروں کی آگ سے علیحدہ ہوکر ٹوٹتے ہیں.وہ خود ستارے نہیں ہوتے.بلکہ ستاروں سے روشنی گرتی ہے کیونکہ ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں اورشہب کاگرنا اسی طرح ہوتاہے جیسے ایک چنگاری آگ سے لی جاتی ہے.وَقِیْلَ اَرَادَ بِالرُّجُوْمِ الظُّنُوْنَ الَّتِیْ تُحْزَرُومِنْہُ وَ یَقوْلُوْنَ خَمْسَۃٌسَادسُہُمْ کَلْبُہُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ.اوربعض محققین نے یہ کہاہے کہ رجوم سے مراد وہ خیالات ہیں جو اپنے قیاس سے بغیر دلیل کے انسان بنالیتا ہے اورانہی معنوں میں قرآن میں لفظ رجمًا بالغیب استعمال ہواہے.یعنی وہ غیب کے متعلق صرف اندازے لگاتے ہیں.(اس آیت کی تفسیر اگلی آیت کے ساتھ دیکھیں)
Page 239
اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ۰۰۱۹ (ہاں )مگرجو شخص (وحی الٰہی کی کوئی )سنی ہوئی بات (جس کااعلان ہوچکاہو)چُرالے تو (یہ اورصورت ہے اوراس صورت میں بھی)ایک روشن شعلہ اس کا پیچھاکرے گا.حلّ لُغَات.اِسْتَرَقَ.اِسْتَرَقَ سَرَقَ سے باب افتعال ہے.اورسَرَقَہُ وَمِنْہُ الشَّیْءَ کے معنے ہیں.اَخَذَہُ خُفْیَۃً مِنْ حِرْزٍ.کہ کسی چیز کو محفوظ جگہ سے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہوئے لے لیا.أوِالسِّرْقَۃُ اَخْذُ الشَّیْءِ فی خَفَاءٍ وَحِیْلَۃٍ.نیز حیلہ سے مخفی طور پر کسی چیز کو نکال لینے کانام بھی سرقہ ہے اوراِسْتَرَقَ السَّمْعَ کے معنے ہیں.اِسْتَمَعَ مُسْتَخْفِیًا.پوشیدہ ہوکرکسی بات کو سنا.اَلْکَاتِبُ بَعْضَ الْمُحَاسَبَاتِ.لَمْ یُبْرِزْہُ.محرر نے اپنے بعض حسابات کو چھپایایعنی ظاہر نہ کیا.(اقرب) اَلسَّمْعُ.السَّمْعُ یہ سَمِعَ یَسْمَعُ کامصدر ہے.اورسَمعَ الصَوْتَ یَسْمَعُ سَمعًا کے معنے ہیں.اَدْرَکَہُ بِحَاسَّۃِ الْاُذُنِ.آواز کوکان کی حس کے ساتھ محسوس کیا.اوراَلسَّمْعُ کے معنے ہیں.حِسُّ الْاُذُنِ.شنوائی.وَالْاُذُنُ.مَاوَلَج فِیْہَا مِنْ شَیْءٍ تَسْمَعُہُ اورجو آواز کان میں پڑے اس پر بھی سمع کالفظ بولتے ہیں.اَلذِّکْرُ الْمَسْمُوعُ سنی ہوئی بات.لفظ سَمْعٌ واحد اورجمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے کیونکہ دراصل یہ مصدر ہے.جو قلّت اورکثرت کااحتمال رکھتاہے.اس کی جمع اَسماعٌ ہے.(اقرب) اَلسَّمعُ.قُوَّۃٌ فی الْاُذُنِ بِہٖ یُدْرِکُ الْاَصْوَاتَ یعنی سمع کان کی ایک قوت (شنوائی)کانام ہے جس کے ذریعہ سے انسان آواز کو معلوم کرتاہے.وَفِعْلُہُ یُقَالُ لَہُ السَّمْعُ اَیْضًا.اورسننے کے فعل کانام بھی سمع رکھاجاتاہے وَیُعَبَّرُ تَارَۃً بِالسَّمْعِ عَنِ الْاُذُنِ.اور کبھی لفظ سمع بول کر کان مراد ہوتاہے.وَتَارَۃً عَنْ فِعْلِہِ کَالسِّمَاعِ اور کبھی لفظ سمع سے اس کافعل مراد لیاجاتاہے.جیسے اِنَّہُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ.کہ ان کو سننے کے فعل سے روک دیاگیاہے.وَتَارَۃً عَنِ الْفَھْمِاور کبھی لفظ سمع سے مراد بات کاسمجھناہوتاہے.جیسے کہتے ہیں.لَمْ تَسْمَعْ مَاقُلْتُ کہ جو میں نے کہاتو نےنہیں سمجھا.وَتَارَۃً عَنِ الطَّاعَۃِ اور کبھی اس سے مراد اطاعت ہوتی ہے.(مفردات) اَتْبَعَہ.اَتْبَعَہُ تَبِعَ سے ہے.اور تَبِعَ کے معنے ہیں.سَارَفِی إِثْرِہِ.اس کے قدموں کے نشانات پر چلا.مَشَی خَلْفَہُ اَوْمَرَّبِہِ فَمَضٰی مَعَہُ.اس کے پیچھے چلایااس کے پاس سے گزرا.اورپھر ساتھ چل پڑا.اَتْبَعَہُ تَبِعَہُ وَذَالکَ اِذَاکَانَ سَبَقَہُ فَلَحِقَہُ اس سے پیچھے رہ گیااورپھر اس سے جاملا (اقرب).
Page 240
شِھَابٌ.شُعْلَۃٌ مِنْ نَارٍ سَاطِعَۃٍ.بھڑکتی ہوئی آگ کا شعلہ.اَوْکُلُّ مَضِیْئٍ مُتَوَلَّدٌ مِنَ النَّارِ یاہرچمکتی ہوئی چیز جو آگ سے پیداہو.وَمَا یُرٰی کَاَنَّہُ کَوْکَبٌ اِنْقَضَّ.ٹوٹتاہواستارہ.وَقَدْ یُطْلَقُ عَلَی الْکَوْکَبِ اَوِ الدَّرَارِیْ مِنَ الْکَوَاکِبِ لِشِدَّۃِ لَمَعَانِہاَ.اور کبھی شھاب کالفظ ستارے پر یاچمکتے ہوئے ستاروں پر ان کی شدت چمک کے باعث بولاجاتاہے.یُقَالُ اِنَّ فُلَانًا شِہَابُ حَرْبٍ اِذَاکَانَ مَاضِیًا فِیْہَا اوراس شخص کو جولڑائی میں تیز ہو.اورجہاں جائے مارتاچلاجائے شِہَابُ حَرْبٍ کہتے ہیں.تُطْلَقُ الشُّھُبُ عَلیٰ ثَلَاثِ لَیَالٍ وَھِیَ اللَّیَالِیْ البِیْضِ.اورشہب کالفظ تین پوری چاندنی راتوں (۱۳.۱۴.۱۵)پر بھی بولتے ہیں.پس شہاب مجازاً ان چیزوں کے لئے استعمال ہوتاہے جو روشن ہوں اوراسی طرح ان لوگوں کے لئے بھی جو چست ہوں اورکام میں خوب ہوشیار ہوں.(اقرب) الشَّہابُ.الشُّعْلَۃُ السَّاطِعَۃُ مِنَ النَّارِ الْمُوْقَدَۃِ جلتی ہوئی آگ کاروشن شعلہ.وَالشُّعْلَۃُ السَّاطِعَۃُ مِنَ الْعَارِضِ فِی الْجَوِّ.فضا میں کسی چیز کے گزرنے کے باعث کسی روشنی اورشعلے کے پیدا ہونے کو بھی شہاب کہتے ہیں.(مفردات) مبین.واضح کرنے والا اورواضح اور ظاہر.مزید تشریح کے لئے دیکھیں سورۃ حجر آیت نمبر۲.تفسیر.بروج کے مختلف معانی.بعض نے بروج کے معنے ستاروں کے کئے ہیں.جیسے قتادہ نے (بحر محیط.درمنثور.ابن کثیرزیر آیت وَلَقَدْجَعَلْنَا فِی السَّمَآئِ بُرُوْجًا)لیکن لغت میں بروج جس کامفرد بُرج ہے اس کے معنے ستاروں کی منزل کے ہیں یعنی جن دائروں میں ستارے چکر لگاتے ہیں.اس کے علاوہ بُرج کے معنے جیساکہ اوپر بتایاگیاہے.محل اورقلعہ کے بھی ہیں.علماء اد ب میں سے بھی زجاج نے بُرج کے معنے کوکب یعنی ستارہ کے کئے ہیں.(تاج العروس ) بعض مفسرین نے بروج کے معنے ستاروں کے کئے ہیں جن مفسرین نے بُرج کے معنے ستاروں کے کئے ہیں.وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں.کہ چونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتاہے.اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ا۟لْكَوَاكِبِ ( الصّافات:۷)ہم نے ورلے آسمان کو ستاروں کی زینت کے ساتھ مزین کیاہے.اس سے معلوم ہوتاہے کہ یہاں بُروج سے مراد ستارے ہیں.اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض ائمہ نے بروج کے معنے کواکب یعنے ستاروں کے کئے ہیں.لیکن مذکورہ بالاآیت سے جو استدلال کیاگیاہے.وہ یقینی نہیں.کیونکہ ممکن ہے کہ وَ زَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ میں دوسرامضمون ہو اورآیت کامفہوم یہ ہو کہ ہم نے آسمان میں ستاروں کی منازل بنائیں.اوران میں چلنے کے لئے
Page 241
ستارے بنائے جن کی وجہ سے آسمان خوبصورت نظرآتاہے.بروج کے معنی ستاروں کے کرنا ضروری نہیں پس جبکہ ضروری نہیں.کہ اس آیت کے یہی معنی ہوں.کہ بروج ہی سے زینت کااظہار کیاگیاہے.بروج کے معنی ستارے کرنے کی کوئی خاص مجبوری نہیں ہے.کلام الٰہی کی حفاظت اور آسمانوں کی حفاظت کا جوڑ بہرحال بروج سے مراد خواہ متداول معنی یعنے ستاروں کی منازل کے کئے جائیں یاستاروں کے معنے لئے جائیں.اصل سوال یہ ہے کہ قرآن کریم یا اس سے پہلے کی کتب سماوی کی حفاظت اورآسمانوں کی حفاظت کا آپس میں جوڑ کیاہے.اورکیوں کلام الٰہی کی حفاظت کے ذکر کے بعد آسمانوںکی حفاظت کا ذکر کیاگیاہے.مفسرین نے اس بارہ میں مختلف خیالات کااظہار کیاہے.جن میں سے بعض محض قصوں کی حیثیت رکھتے ہیں اورنہ ان کاکوئی ثبوت ہے اورنہ خدائی کلام سے وہ کوئی دور کی بھی مناسبت رکھتے ہیں.مگربہرحال ان قصوں اورحدیثوں اورتفسیروںکے متعلق میں اصل مضمون بیان کرنے کے بعد اپنی تحقیق بیان کروں گاپہلے میں وہ معنے بیان کردیتاہوںجومیرے نزدیک قرآن کریم کے سیاق و سباق کو دیکھ کر ان آیات سے نکلتے ہیں.ظاہری نظام اور روحانی نظام میں مماثلت قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتاہے کہ وہ ظاہری نظام اور روحانی نظام میں ایک شدید مماثلت اورمشابہت کادعویٰ کرتاہے اوربار بار روحانی عالم کے سمجھانے کے لئے جسمانی عالم کی مثالیں دیتاہے.کبھی الہام کو پانی کے مشابہ قرار دے کر اس کے اثرات اورکلام الٰہی کے اثرات کی مشابہت کو پیش کرتاہے.کبھی زمین و آسمان کے تعلقات سے روح اور جسم کے تعلقات پر روشنی ڈالتاہے.کبھی روشنی اور آنکھ کے تعلقات سے یہ نتیجہ نکالتاہے کہ ا ندرونی قابلیتوں کے بغیر صداقت نفع نہیں دیتی.غرض بیسیوں بلکہ سینکڑوں سبق جسمانی نظام سے حاصل کرنے کے لئے وہ ہمیںتوجہ دلاتاہے اس آیت میں بھی ایسی ہی مشابہت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.زمین کے رہنے والوں کوایک آسمان اپنے سروں پر نظر آتاہے.اس میں ستاروں کاایک نظام ہے جو اپنے اپنے وقت پر اوراپنے اپنے دائرہ میں کام کررہے ہیں.اس نظام کو بدلنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا.اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کے سامان موجود ہیں.ظاہری نظام کی مثال سے روحانی نظام کو پیش کیا گیا ہے اسی مثال کو لے کر قرآن کریم میں متعدد بار روحانی آسمان کے نظام کو پیش کیا گیاہے چنانچہ اس جگہ بھی میرے نزدیک اسی نظام کی طرف اشارہ ہے.فرماتا ہے
Page 242
کہ جس طرح جسمانی نظام مضبوط بنیادوں پر قائم ہے روحانی نظا م بھی مضبوظ بنیادوں پر قائم ہے اورہم نے اسے بھی جسمانی نظام کی طرح کئی طبقوں میں تقسیم کیاہے.جو اس کے اوپر کے طبقے ہیں.وہ تو محفوظ ہیں ہی.جونیچے کاطبقہ ہے.اس میں شرارت کاامکان ہوسکتاتھا.سواسے بھی ہم نے ستاروں سے مزین کیاہے اوران کے ذریعے اس نچلے آسمان کی حفاظت کی ہے.جس طرح جسمانی ستاروں سے جسمانی آسمان کا قیام ہے اس طرح روحانی ستاروں سے روحانی آسمان کا مطلب یہ کہ جس طرح ظاہری آسمان کا نچلا حصہ ایک نظام اوراس کے ماتحت کے ستاروں اور سیاروں کانام ہے اسی طرح روحانی آسمان کانچلا حصہ بھی ایک نظام اورچندستاروں کانام ہے جوروحانی آسمان کی حفاظت کرتے ہیں.جس طرح جسمانی ستاروں کے وجود سے جسمانی آسمان کاقیام ہے اسی طرح روحانی ستاروں کے وجود سے روحانی آسمان کاقیام ہے.جس طرح ظاہری ستارے ظاہری آسمان کی زینت کا موجب ہیں ایسے ہی روحانی ستارے روحانی آسمان کی زینت کا بلکہ جس طرح جسمانی سماء الدنیا ستاروں کے مجموعہ کانام ہے اور وہی اس کی زینت کاموجب ہیں.اسی طرح روحانی سماء الدنیاروحانی ستاروں کے مجموعہ کانام ہے.اور وہی اس کی زینت کاموجب ہیں.اور جس طرح جسمانی ستارے سماء الدنیا کی حفاظت کاموجب ہیں.کیونکہ وہ اس کے اجزاء ہیں.اگر ان میں خرابی ہوتوسارانظام درہم برہم ہو جاتا ہے.اسی طرح روحانی ستارے روحانی سماء الدنیا کی حفاظت کاموجب ہیں.اگر ان میں خرابی ہو.توروحانی سماء الدنیا درہم برہم ہوجائے.اس لئے جب کو ئی اس میں خرابی پیداکرناچاہے.خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر مارپڑتی ہے اورآگ اورپتھر برستے ہیں.جیساکہ رجوم اورشھب کے الفاظ سے بتایاگیاہے.آگ اور پتھر کے محاورہ سے مرادآسمانی عذاب ہوتا ہے یہ آگ اورپتھر کامحاورہ آسمانی عذاب کے متعلق عام ہے چنانچہ قرآن کریم میں کفار کی نسبت آتاہے کہ وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلاکئے جائیں گے.جو آگ اورپتھر وں پر مشتمل ہوگا.چنانچہ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ١ۖۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ (البقرۃ:۲۵) اس آگ سے بچو جس میں دوزخی لوگ اورپتھر ڈالے جائیں گے یعنے اس آگ کے بھڑکانے کاروحانی موجب تو گنہ گار انسان ہوں گے اور جسمانی ذریعہ پتھر ہوں گے.غرض قرآن کریم سے معلوم ہوتاہے کہ عذاب الٰہی کو آگ اورپتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے اوران آیات میں بھی شہب اور رجم کا ذکرکرکے یہی بتایاہے کہ ایسے آدمی عذاب الٰہی
Page 243
میں مبتلاہوں گے.روحانی نظام کو جسمانی نظام سے قرآن کریم میں مشابہت اب میں یہ بتاتاہوں کہ قرآن کریم میں روحانی نظام کو جسمانی نظام سے مشابہت دی ہے.سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ رسول کریمؐ کی نسبت فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا.(الاحزاب:۴۶،۴۷)اے نبیؐ ! ہم نے تجھے گواہ اوربشارت دینے والا اورڈرانے والااوراللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اورروشن سورج بناکر بھیجاہے.جیساکہ دوسری آیات سے ظاہر ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نظام نبوت کے لئے بطور مرکز کے ہیں.جس طرح سورج نظام دنیاوی کے لئے بطورمرکز کےہے.پس آپؐ کو سورج کہہ کر بتایاہے کہ روحانی آسمان میں تیرے سوااورستارے اورچاند بھی ہیں.جو سب کے سب تیرے گر د گھومتے ہیں.یہ ستارے اورچاند دوسرے انبیاء ہیں جن کی نبوتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے لئے بطورارہاص کے تھیں اورسب نبی آپؐ کے گردستاروں کی طرح چکر کھاتے ہیں.جس طرح وسیع روحانی نظام میں دوسرے انبیا ء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بمنزلہ ستاروں کے تھے اورآپؐ ان میں سورج کے طور پرتھے.اسی طرح ایک چھوٹے دائرہ میں آپ بمنزلہ سور ج کے تھے.اورآپ ؐ کے صحابہ بمنزلہ ستاروں کے تھے.آنحضرت ؐ اپنے صحابہ کے درمیان ایک سورج کی طرح تھے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اَصْحَابِیْ کَاالنُّجُوْمِ بِأَ یِّھِمُ اقْتَدَیْتُمُ اھْتَدَیْتُمْ.(مشکوٰۃ کتاب المناقب و الفضائل باب مناقب الصحابۃ ) میرے صحابہ میرے گرد ایسے ہیں جس طرح سورج کے گرد ستارے اورجس طرح ستارے جب تک سورج کے نظام سے وابستہ رہتے ہیں.لوگوں کو راہ دکھانے کاموجب ہوتے ہیں.اسی طرح میرے اصحاب میں سے جو میرے نظام سے وابستہ رہیں گے وہ ستاروں کاکام دیں گے.جزوی اختلافات کے باوجود ان میں سے جس کی اتباع بھی تم کروگے ہدایت پاجائو گے.نظام کو سورج چاند اور ستاروں سے مشابہت اس امر کامزید ثبوت کہ روحانی نظام کو سورج چاند ستاروں سے مشابہت دی جاتی ہے.حضرت یوسف علیہ السلام کی رویاء سے بھی معلوم ہوتاہے.قرآن کریم میں آتاہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ (یوسف :۵)اے میرے باپ میں نے گیارہ ستاروں کو اورسورج اورچاند کو دیکھاکہ میری فرمانبرداری میں مشغول ہیں.اور اس کی تعبیر آگے چل کراس طرح بیان ہوئی ہے.وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا
Page 244
لَهٗ سُجَّدًا١ۚ وَ قَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ١ٞ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا(یوسف :۱۰۱)یعنے یوسف کے بھائیوں کے آنے کے بعد جب ان کے ماں باپ بھی آگئے اورانہو ںنے اپنے ماں باپ کو تخت پر اپنے پاس بٹھایا اوروہ شکرانہ کے طورپر سجدہ میں گرگئے.توحضرت یوسف ؑ نے فرمایا کہ اے میرے باپ! یہ میری اس خواب کی جو میں پہلے زمانہ میں دیکھ چکاہوں تعبیر ہے.میرے رب نے اس خواب کو آخر سچاکرہی دکھایا کہ باپ ماںاو ربھائیوں کو میرے ماتحت علاقہ میں لے آیا.الہامی زبان میں خاندانی یا مذہبی نظام کو نظام شمسی سے مشابہت دی جاتی ہے اس خواب اور اس کی تعبیر سے جو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے ظاہر ہے کہ الہامی زبان میں خاندانی یامذہبی نظام کونظام شمسی سے مشابہت دی جاتی ہے.اور میرے نزدیک آیت زیر بحث میں بھی یہی معنے مرادہیں.کلام الٰہی کی حفاظت کے ذکر کے ساتھ نظام شمسی کی تمثیل اس تمہید کے بعد میں بتاناچاہتاہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلام الٰہی کی حفاظت کا ذکر فرمایاتوساتھ ہی نظام شمسی کی تمثیل سے یہ سمجھایا کہ کس طرح یہ حفاظت کی جائے گی.چنانچہ بتایاکہ ظاہری مادی نظام میں جس طرح ایک آسمان ہے یعنی مختلف ستاروں کاایک مجموعہ ہے.اسی طرح نظام روحانی بھی مختلف انبیاء کاایک مجموعہ ہے.اوروہ روحانی آسمان کہلاتاہے.ظاہری ستارے ظاہری آسمان کی حفاظت اور زینت کا موجب ہیں.ہر نبی روحانی آسمان کی زینت اور حفاظت کا موجب ہوتا ہے جس طرح ہرستارہ اپنی اپنی جگہ اس آسمان کے لئے زینت کاموجب ہے اورکشش ثقل کے اصول سے اور دیگرایسے ذرائع سے جن کاعلم شاید بندوں کو ابھی تک حاصل نہیں ہوااس کی حفاظت کررہاہے اسی طرح ہر نبی نظام روحانی کے لئے زینت کاموجب ہے اور اس کی حفاظت کاموجب ہے.ایک نبی بھی نہیں جوبے موقع یا بلاضرورت آیاہو.ہرنبی کاایک معین کام تھا جو اس کے بغیر کوئی نہیں کرسکتاتھا.اورہرنبی نے آسمان روحانی کی حفاظت کاکام انجام دیاہے اورکلام الٰہی کی خدمت کی ہے.اوراس کی حقیقت اوربرتری اورتاثیر کو اپنے وجود سے اوراپنے تابعین کے وجود سے ثابت کیا ہے اوروہ شیطانی صفت لو گ جنہوں نے خدائی کلام کو بگاڑناچاہاانہیں شکست دی اورذلیل کیا.گویاوہ ان پر پتھر اورآگ کی طرح گرے اورانہیں ناکام کردیا.نظام جسمانی میں تو شیطانوں کا تصرف ہے لیکن آسمان پر نہیں اس میں یہ بھی بتایاہے کہ جس طرح
Page 245
نظام جسمانی میں شیطانوں کایعنی برے انسانوں کازمین پر توتصرف ہے کہ وہ اس جگہ ظلم اور فساد پیداکرتے رہتے ہیں.لیکن آسمان پرکوئی تصرف نہیں.ظالمانہ طور پر وہ دنیوی نعمتوں پر توقابض ہوجاتے ہیں.لیکن آسمانی نعمتوں جیسے ستاروں کی تاثیرات نورہوا وغیرہ کے فوائدسے لوگوں کومحروم نہیں کرسکتے اورنہ آسمان پر ان کاکوئی اختیار ہے.سورج چاند ستارے ان کے تصرف سے بالا ہیں.یہی حال روحانی عالم کا ہے کہ شیطانوں کاکوئی تصرف انبیاء اوران کے کامل متبعوںپر نہیں ہوسکتا.جیسے دوسری جگہ فرمایا.اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ.(الحجر:۴۳) میرے کامل بندوں پر تیراکوئی اثر اورقبضہ نہ ہوگا.نیز جس طرح آسمان جسمانی کی نازل کردہ برکات پر شیطانوں کاکوئی تصرف نہیں.و ہ روشنی ،ہوااورتاثیرات سماوی میں روک نہیں ڈال سکتے اسی طرح روحانی آسمان یعنی انبیاء کے ذریعہ سے ظاہر ہونے والے فیض یعنی کلام الٰہی اورمعجزات ونشانات پر بھی شیطانوں کوکوئی تصرف حاصل نہیں ہوتا.اللہ تعالیٰ آسمان روحانی یعنے انبیاء کو اوران کی تاثیرات کو کلی طورپر شیطانی دخل سے پاک رکھتاہے.یہ گویا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ کی تشریح فرمائی ہے.جملہ انبیاء مسِ شیطان سے پاک ہیں تعجب ہے اس آیت کی موجودگی میں مسلمان اس عقیدہ پر قائم ہیں کہ سوائے حضرت عیسیٰ اوران کی ماں مریم کے کوئی بھی خواہ نبی ہو مس شیطان سے پاک نہیں(قرطبی زیر آیت وانی اعیذھا بک..).حالانکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آسمان روحانی کے محفوظ ہونے کا ذکر فرماتا ہے جس میں آدم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی اور ان کے کامل اَتباع شامل ہیں.شہاب کے ساتھ مبین کی صفت لگانا ظاہر کرتا ہے کہ جسمانی نظام کی حفاظت مراد نہیں اس کے بعد فرماتا ہے اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ الآیہ.ہاں اگر کوئی سنی سنائی بات چرالے تو اس پر شہاب مبین گرتاہے اس آیت نے صاف واضح کردیاکہ یہاں آسمان اور نظام شمسی کو بطور تمثیل بیان کیاگیاہے ورنہ جسمانی نظام مراد نہیں کیونکہ اول تو سنی سنائی بات کے چُرالینے کاآسمان جسمانی سے کوئی تعلق نہیں.دوسرے شہابٌ کے ساتھ جومبین کی صفت لگائی ہے.اس کاجسمانی شہاب سے کوئی تعلق نہیں.شہاب کے معنی کیونکہ شہاب یاتوآگ کے شعلے کو کہتے ہیں یاوہ روشنی جو آسمان پرنظر آتی ہے اوریوں معلوم ہوتاہے کہ جیسے کوئی ستارہ ٹوٹا.ان دونوں چیزوں کے لئے مبین کی صفت بے محل اوربے معنی ہے.شہاب سے مراد انبیاء لئے جاویں تو مبین کی صفت بر محل اور مناسب معلوم ہوتی ہے لیکن اگر روحانی آسمان مراد لیاجائے اورشہاب سے مراد انبیاء لئے جائیں جو آسمانی تائیدات اورنشانات لے کر آتے ہیں
Page 246
اورکلام الٰہی میں رخنہ ڈالنے والوں کے خلاف کام کرتے ہیں.تومبین کی صفت بالکل برمحل اورمناسب حال معلوم ہوتی ہے.کیونکہ اس صورت میں شہاب کے ساتھ مبین کے لفظ کا استعمال ایک مزید فائدہ کے لئے اور ایک روشن نشان کے معنوں پردلالت کرنے کے لئے ہے.اوربتایاہے کہ اللہ تعالیٰ کاکلام جب تک آسمان پر ہوتاہے اورجب تک روحانی آسمان کے اجرام یعنی انبیاء پر نازل ہوتاہے اس وقت تک تو بالکل محفوظ ہوتاہے لیکن نچلے آسمان پر نازل ہونے کے بعد جب بنی نوع انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور مسموعات میں سے ہو جاتا ہے یعنی سنی ہوئی باتوں میں شامل ہو جاتا ہے.پردئہ غیب سے پردئہ شہود پر آجاتاہے.اورلوگ ایک دوسرے کو وہ کلام سنانے لگ جاتے ہیں.شیطانوں کا انبیاء کے کلام کو چرانا توشیطان یعنے انبیاء کے دشمن اس کلام کو چرالیتے ہیں یعنی بغیر حق کے اس کلام کو لے لیتے ہیں اس کاغلط استعمال کرتے ہیں.انبیاء اور ان کے اتباع کا چوروں کے فریب کو ظاہر کرنا تب یاتو وقت کے نبی کی معرفت ان پر آسمانی عذاب نازل ہوتاہے یاپھر انبیاء اوران کے اتباع اس کلام کی اصل حقیقت کو دنیاپر ظاہرکرکے ان چوروں کے فریب کو ظاہرکردیتے ہیں.اوروہ ذلت کے عذاب میں مبتلاہوتے ہیں اورسچائی کی روشنی میں ان چوروں کی حقیقت ظاہر ہوجاتی ہے.کلام الٰہی کے چرالینے سے مراد اس آیت میں کلام کے چرالینے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح چورناحق دوسرے کے مال کو لیتا ہے.اسی طرح وہ کلام الٰہی کو ناحق لیتے ہیں یعنے اس کے معنوں کو سمجھ کر ایمان نہیں لاتے بلکہ صرف اس لئے کلام کو اخذ کرتے ہیں.تااس کاناجائزاستعمال کریں اورا س کے غلط معنے کرکے لوگوںکو گمراہ کریں.جس طرح چوری کا لباس چور کے بدن پر ٹھیک نہیں آتا اسی طرح انبیاء کی تعلیم چوروں کے معتقدات کے ساتھ مطابق نہیں آتی کلام کی چوری کرنے کے یہ معنی بھی ہیں کہ انبیاء کی بعض تعلیمات کو اس زمانہ کے لوگ اپنا بنا کر پیش کرتے ہیں.اوراس طرح یہ ثابت کرناچاہتے ہیں کہ گویا ان کو بھی انہی علوم پر دسترس ہے.جن پر انبیاء کو ہے بلکہ انبیاء نے ان کے علوم چرالئے ہیں.لیکن جس طرح چوری کالباس پہچاناجاتاہے.وہ چور کے بدن پر ٹھیک نہیں آتااسی طرح انبیاء کی چوری کی ہوئی تعلیم چونکہ ان چوروں کے دوسرے معتقدات کے ساتھ مطابق نہیں آتی.جب انبیاء اوران کے اتباع ان کی حقیقت کو کھولتے ہیں تو ان کی چوری ظاہرہوجاتی ہے.ہر نبی کا کلام چرایا گیا یہ دونوں امر سب نبیوں کے ساتھ پیش آئے ہیں.انبیاء کی اعلیٰ تعلیمات کولوگ اپنی
Page 247
تعلیمات ظاہرکرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں.اور اس طرح ان کی اہمیت کو گراناچاہتے ہیں.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حملہ سب نبیوں سے زیادہ ہواہے.مسیحی اور آریہ مصنفین کے قرآن کریم کی تعلیمات پر بے جا اعتراضات مسیحی اور آریہ مصنفین کثرت سے قرآن کریم کی تعلیمات کے ٹکڑے لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اُن کے مذاہب کی کتب میں پائے جاتے ہیں.لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور کو ظاہر کیا جاتا ہے اوربتایاجاتاہے.کہ جس ٹکڑے کو تم نے لے لیاہے.وہ تو ایک لمبی زنجیر کی کڑی ہے.اوروہ ساری زنجیر ایسے وسیع مطالب رکھتی ہے کہ تمہارے خواب و خیال میں بھی موجود نہیں.توان کی پردہ دری ہوجاتی ہے.مصنف ینابیع الاسلام کے قرآنی مطالب پر اعتراضات ایسے ہی حملہ کرنے والوں میںیَنابِیع الاسلام کامصنف ہے.جس نے نہایت دیدہ دلیری سے قرآنی مطالب کے ٹکڑوں کو لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ گویاوہ پہلے مذاہب کی کتب سے لئے گئے ہیں.حالانکہ وہ ٹکڑے ایک کُل کاحصہ ہیں اوران کو کُل سے الگ کیاہی نہیں جاسکتا.اوراس کُل میں وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کسی اورشئے کاجزو قراردیاہی نہیں جاسکتا.اس کے لئے دیکھو سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پر بحث.جسے مصنف یَنابِیع الاسلام نے زردشتی کتب کی چوری قرار دیاہے.(یَنابِیع الاسلام فصل پنجم) دوسرے معنے جوکلام چرالینے کے میں نے یہ کئے ہیں کہ الٰہی کلام کے بعض ٹکڑوں کو لے کر غلط طور پر انہیں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں.یہ بھی سب نبیوں سے ہوتا چلاآیا ہے.ہرنبی کے الہام کو اس کے مخالف بگاڑ کر پیش کرتے رہے ہیں.تالوگوں کو ان کے خلاف جوش دلائیں وہ اصل مطلب کو بگاڑ بگاڑ کر ان کے الہامات کو پھیلاتے رہے ہیں.اورچوروں کی طرح ان کا ناجائزاستعمال کرتے رہے ہیں.یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی نشانات او ر معجزات سے مدد کی.خدا تعالیٰ کا قہری نشانوں اور قدرت نمائی سے دشمنوں کو ہلاک کرنا اورایک طرف تودلائل سے معترضین کے غلط معنوں کو ردّ کیا.اوردوسری طرف قہری اورقدرت نمائی کے نشانات کے ذریعہ سے اپنے نبیوں کی تائید کرکے ان کے دشمنوں کو ہلاک کروایا اور اس طرح اپنے کلام کی حفاظت کی.بعض دفعہ نبی کے اتباع بھی دین سے بے بہرہ ہوکر اوربے دینی کاشکارہو کر دین کو بگاڑ لیتے ہیں اورکلام الٰہی کے معنی کچھ سے کچھ کردیتے ہیں اوراس کی خوبیوں کو غلط تفسیروں سے چھپادیتے ہیں.تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے
Page 248
اتباع میں سے کسی کو شہاب ثاقب یاشہاب مبین بناکر یعنے اپنا تازہ الہا م دے کر اوراپنے نشانات سے مؤیّدکرکے آسمان روحانی سے نازل کرتاہے تاوہ ایسے شیاطین کی سرکوبی کرکے کلام الٰہی کو پھر اس کی اصل جگہ پر لے آئیں اوراس طرح وہ کلام جو بکھرجانے اورتباہ ہونے کے خطرہ میں پڑ گیاتھاپھر محفوظ ہوجائے.اوراس کے صحیح مطالب پھرلوگوں پر آشکار ہو جائیں.اوپر کے مضمون سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان آیات میں ستاروں سے انبیاء مرادہیں اورشہاب مبین یاشہاب ثاقب سے مراد وقت کانبی ہے.کیونکہ ہرنبی ایک ستارہ ہے اورآسمان روحانی کے لئے زینت کاموجب ہے لیکن ہرنبی ہروقت شہاب کاکام نہیں دے رہا.یعنے وہ شیطان جو دین میں رخنہ اندازی کررہے ہیں ان کی ہلاکت کاموجب نہیں بن رہا.یہ کام صرف وقت کانبی کرتاہے.یاوہ نبی کرتاہے جس کی نبوت زندہ ہو.اورجس کی شریعت قابل عمل ہو ایسے نبی کی امت میں خرابی پیداہوکر اگردوسراتابع نبی مبعوث بھی ہو تب بھی چونکہ اس کی قوت قدسیہ اس تابع نبی کے ذریعہ سے کام کررہی ہوتی ہے.وہ شہاب ہی کہلاتاہے.چنانچہ اس تشریح کے ماتحت حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہماالسلام اور دوسرے سابق انبیاء آسمان روحانی کے ستارے توہیں.مگرشہاب نہیں.کیونکہ اس وقت شیطانوں کے مارنے کے لئے اللہ تعالیٰ انہیں استعمال نہیں کررہا.مگرمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہاب ہیں کیونکہ ان کے ا ظلال یہ کام قیامت تک کریں گے.اس آیت میں نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کی حقیقت بتائی گئی ہے خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَکی حقیقت بتائی گئی ہےاوربتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس کلام کی جو اس کی طرف سے اتراہو اورالذکرکہلانے کامستحق ہو کس کس طرح حفاظت کرتاہے.ظاہر میں بھی اورباطن میں بھی اورنبی کے زمانہ میں بھی اوراسکے بعد بھی.اوریہ کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت بھی ان سب سامانوں کے ذریعہ سے کرے گا.کلام الٰہی کی حفاظت کا ذکر سورۃ حج میں یہ آیات گویاسورہ حج کی مندرجہ ذیل آیات کے ہم معنے ہیں.وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ١ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ١ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ(الحج:۵۳)یعنی ہرنبی اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ گزراہے کہ جب اس نے خدا کاکلام پڑھ کر لوگوںکو سنایا شیطان نے ہمیشہ ہی ان کے سنائے ہوئے کلام میں اپنی طرف سے کچھ معنے شامل کرکے لوگو ں کو یہ بدلے ہوئے مضامین سنانے شروع کئے.آخر اللہ تعالیٰ نے اس کی ملائی ہوئی باتوں کو تو مٹا دیا اور خدائی کلام کو قائم رکھا یعنے لوگ کلام الٰہی کو بگاڑ بگاڑکر لوگوں کوگمراہ توکرتے ہیں مگر آخر کلام کی سچائی ظاہر ہوجاتی ہے.
Page 249
اوروہ لوگ ناکام و نامراد ہوجاتے ہیں.ان دونوں آیتوں میں شدید مشابہت ہے.سورہ حجر میں بھی یہ ذکر ہے کہ روحانی آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے.اوریہاں بھی یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام الٰہی کی حفاظت کرتاہے.سورہ حجر میں بھی ہے کہ شیطان آسمان میں دخل دیناچاہتے ہیں اورسورہ حج میں بھی ہے کہ وہ کلام الٰہی میں دخل دینا چاہتے ہیں سورہ حجر میں بھی ہے کہ دخل دینے والوں کو خداتباہ کردیتاہے.اورسورہ حج میں بھی ہے کہ کلام الٰہی کو بگاڑنے کی سعی کرنے والوںکے فعل کو خدا تعالیٰ مٹادیتاہے.غرض دونوں کے مفہوم سے صاف معلوم ہوتاہے کہ دونوںمیں ایک ہی مضمون بتایاگیاہے.اورجب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسمانوں کی زینت اوران کی حفاظت کابیان ہرجگہ کلام الٰہی کے ذکرکے بعد بیان ہواہے.توصاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ روحانی آسمان اوراس کی حفاظت کا ذکر ہے.نہ کہ جسمانی آسمان اوراس کی حفاظت کا.جسمانی آسمان سے صرف تشبیہ دی گئی ہے.اس سے زیادہ اس سے ا س کاکوئی تعلق نہیں.ان آیات میں یہ بھی بتایاگیاکہ ذکر محفوظ کی یہ علامت ہے کہ اس کے اند رجب کو ئی دخل دیناچاہے اس کی حفاظت کے لئے شہاب اترتے ہیں پس جس کلام کی حفاظت کے لئے شہاب نہ اتریں مانناپڑے گاکہ اب و ہ کلام محفوظ نہیں رہا.اورالذکر کے مقام سے گرگیاہے.شہاب کے معنے یہ بھی یاد رکھناچاہیے کہ گوشہاب کے تین معنے ہیں(۱)شعلہ (۲)ستاروں کی طرح چمکنے والی روشنی جو آسمانی پتھروں کی رگڑ سے پیداہوتی ہے اور(۳)ستارہ.لیکن اس جگہ ستارہ ہی مراد ہے.کیونکہ دوسری جگہ صافات(ع۱) میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ا۟لْكَوَاكِبِ.وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ (الصافات:۷،۸)یعنی آسمان پر ستارے زینت کے لئے اورحفاظت کے لئے بنائے گئے ہیں.پس حفاظت کاکام ستاروں کے سپر د کیاگیاہے پھرسورہ مُلک میں ہے.وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ (الملک:۶)یعنے ہم نے آسمان قریب کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور ان ستاروں کو شیطانوں پر پتھرائو کرنے کا ذریعہ بنایاہے.ان حوالوں سے معلوم ہوتاہے کہ شہاب ستاروں کاہی نام رکھا گیاہے.شہاب کے پیچھے لگانے سے مراد پس شہاب کے پیچھے لگانے سے یہ مراد ہے کہ جب تک کوئی کلام الٰہی زندہ ہوتاہے اورالذکر کہلانے کامستحق ہوتاہے.کلام الٰہی کی حفاظت کے لئے شہاب بھیجنے سے مراد مامورین کی بعثت اللہ تعالیٰ دشمنوں سے اس کی حفاظت کے لئے شہاب یاستارے یا دوسرے الفاظ میں مامورین بھیجتارہتاہے.اورزیر بحث آیات میں قرآن
Page 250
کریم کی حفاظت کے لئے خاص طور پر اس طریق کے استعمال کاوعد ہ کیاگیاہے اوراس سے زیادہ مضبوط طریق حفاظت کا ناممکن ہے.کیونکہ مامورین نہ صرف نشانات سے شیطانوں کے حملو ں سے شریعت حقہ کی حفاظت کرتے ہیں.بلکہ بوجہ الہام سے مؤیّد ہونے کے ان کی تشریحات سے مومنوںکو کلام الٰہی کے وہ صحیح معنے بھی معلوم ہوتے ہیں.جن کے بارہ میں شک کیاہی نہیں جاسکتااوران کی وجہ سے و ہ ان تفسیری اختلافات سے نجات پاجاتے ہیں جو اس سے پہلے لوگوں کے خیالات کو مشوّش کررہے ہوتے ہیں.کلام الٰہی کی حفاظت کے لئے مامورین کا آنا نہایت ضروری ہے مذکورہ بالا تفصیل سے یہ امر روشن ہو جاتاہے کہ کلام سابق کی حفاظت یعنے اسے شیطانی وساوس سے پاک کرنے اور اس کی زندگی کاتازہ نشانات سے ثبوت دینے کے لئے مامورین کاآنا نہایت ضروری ہے.لیکن افسوس کہ آ ج مسلمان اس فضیلت کے منکر ہیں اورکہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تابع نبی بھی نہیں آسکتا.حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تک کوئی کلام الذکر ہے.اس کی حفاظت اور دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لئے آسمانِ روحانی کے ستارے اورشہاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے رہیں گے.پہلے مذاہب میں انبیاء کی بعثت کا بند ہونا ان کی کتب کے الذکر نہ ہونے کی علامت تھی پہلے مذاہب میں جو انبیاء کی بعثت کاسلسلہ بند ہوگیاہے.یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی کتب الذکر نہیں رہیں.قرآن کریم چونکہ الذکر ہے اورقیامت تک رہے گا.اس کی حفاظت کا یہ ذریعہ بھی قائم رہے گا.اوراس سے اس کادرجہ گھٹتانہیں بلکہ یہ ثابت ہوتاہے کہ قرآن کریم اب تک الذکر ہے.یعنی اللہ تعالیٰ اوربند ہ میں تعلق پیداکرنے کاذریعہ ہے.اس لئے اس کی ظاہری حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مامورین بھیج کر اندرونی اوربیرونی شیطانوں کے حملوں کو دور کرکے اس کی معنوی حفاظت بھی کرتاہے.جو شخص یہ کہتا ہے کہ اب شھاب مبین یعنے آسمانِ روحانی کے ستارے بھیجنے کاسلسلہ قرآن کریم کی حفاظت کے لئے بھی بند ہوگیاہے وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتاہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم اب الذکر نہیں رہااور اس کی حفاظت کے لئے اورشیطانوں کی سرکوبی کے لئے اب روحانی آسمان سے ستاروں کانزول بند ہوگیاہے.یہ خیال کہ پہلے الہاموں کی حفاظت بندے کرتے تھے درست نہیں ایک موجودہ زمانہ کے مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتاہے.اس سے پہلے الہاموں کی حفاظت بندے کرتے تھے.اوراس کے ثبو ت میں اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ اورسو ر ہ مائدہ کی مندرجہ ذیل آیت کو پیش کیا ہے.
Page 251
اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ١ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ(المائدۃ:۴۵) ہم نے تورات کو جس میں ہدایت اورنو ر تھے نازل کیاتھا.اس کے ذریعہ سے وہ انبیاء جو تورات کے مومنون میں شامل تھے.نیز ربانی اوراحبار لوگ یہودیوں کے لئے فیصلے کیاکرتے تھے.کیونکہ ان کے سپر د کتاب اللہ کی حفاظت کی گئی تھی ور وہ اس پر بطورنگران تھے(بیان القرآن زیر آیت انا نحن نزلنا الذکر...).میرے نزدیک یہ استدلال اسی صورت میں درست ہوسکتاتھا.اگراس جگہ نبیوں کا ذکر نہ ہوتامگر اس جگہ تویہ بتایاگیاہے کہ نبیوں کے سپر د تورات کی حفاظت کی گئی تھی اوریہ ظاہر ہے کہ نبی اپنی طاقت سے کام نہیں کرتا.خدا تعالیٰ کی طاقت سے کام کرتاہے.پس اس صورت میں کیونکر کہاجاسکتاہے کہ بندوں کے سپرد تورات کی حفاظت تھی ؟فرض کرو کہ کسی نے تورات کے مضمون کو بدل دیاہوتااورخدا تعالیٰ ایک نبی کو اس کی اصلاح کاکام سپرد کرتا.تووہ نبی غلطی کیونکر معلوم کرسکتاتھا؟خدا تعالیٰ کے الہام کے سوا اس کے پاس اصل حقیقت معلوم کرنے کا کونسا ذریعہ ہوسکتاتھا.اورجب خدا تعالیٰ الہام سے کسی کو کسی غلطی پر اطلاع دے گا.تووہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی نہ کہ بندہ کی طرف سے.یامثلاً چند شیطان اگر اس کلام کے معانی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے اوردنیاکو گمراہ کر تے.تونبی جو معجزات اورنشانات اوربراہین سماویہ سے ان کامقابلہ کرتاتھا.وہ اس کاکام نہیں کہلاسکتا.بلکہ اللہ تعالیٰ کاکام کہلائے گا.پس یہ درست نہیں کہ پہلی کتب کی حفاظت بندوں کے سپرد تھی اورقرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی.اللہ تعالیٰ نے سب ذکروں کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب ذکروں کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے.جیساکہ اوپر کی آیات سے ثابت ہے.ہاں! اگر بعض کام وہ بندوں سے لیتاتھاتو وہ صرف اس کاہتھیار ہونے کی صورت میں وہ کام کرتے تھے.اب قرآن کریم جو سب دنیا میں پھیل گیا اورزبردست حافظہ والوں نے اسے حفظ کیا.یہ بظاہر بندوں کاکام ہے لیکن کوئی نہیں کہہ سکتاکہ قرآن کریم کی حفاظت بندوں کے سپرد ہے.کیونکہ یہ انتظام بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے.حفاظت کے سلسلہ میں قرآن کریم کو دوسری کتب پر فضیلت اس بارہ میں نہیں کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے.اوردوسری کتب کی حفاظت انسان کرتے ہیں.بلکہ اس بار ہ میں ہے کہ وہ ایک محدود عرصہ تک الذکر رہیں اورقرآن کریم قیامت تک کے لئے الذکر ہے اوراس کی تائید کے لئے ہمیشہ مامورین آتے رہیں گے.جبکہ دوسری کتب کی حفاظت اللہ تعالیٰ دیرسے چھوڑ چکا ہے اورشیطانوں کے حملوں سے انہیں بچانے کے لئے اب آسمان سے
Page 252
شہاب نازل نہیں ہوتے.دوسر ی فضیلت اس بارہ میں قرآن کریم کو یہ حاصل ہے.کہ و ہ سب کا سب کلام اللہ ہے یعنے اس کاایک ایک لفظ الہامی ہے.جبکہ پہلی کتب کایہ حال نہ تھا.وہ کلام الٰہی اور تشریح کلام الٰہی کے مجموعہ ہوتے تھے.جیساکہ عہد قدیم کی کتب اور انجیل سے روز روشن کی طرح ثابت ہے.پس ان کتب کے مضمون کی حفاظت کافی سمجھی جاتی تھی.کیونکہ اس زمانہ میں الذکر مفہوم کانام تھا.الفاظ کا نہیں اورخدائی الہام کو انبیاء یاان کے تابع اکثر اپنے الفاظ میں بیان کردیتے تھے.اوراس میں حرج نہ سمجھاجاتاتھا.قرآن کریم کی وحی چونکہ دائمی وحی تھی.اللہ تعالیٰ نے اس کے وقت سے طریق وحی کو بدل دیا.اورخود الفاظ کامحفوظ رکھنا ان کی حرکات سمیت ضروری قرارپایا.پس قرآن کریم کاہرہرلفظ لکھا گیا، یاد کیاگیا اورمحفوظ رکھا گیا.اس قسم کی حفاظت پہلی کسی وحی کو حاصل نہ تھی.نہ اللہ تعالیٰ کے ذریعہ سے.نہ بندوںکے ذریعہ سے.ہاں معنوی حفاظت ایک محدود عرصہ کے لئے اسی طر ح دوسری کتب کوحاصل تھی جس طرح کہ قرآن کو قیامت تک کے لئے حاصل ہے.ظاہری شہب کو انبیاء سے تشبیہ دینے کا مطلب ایک سوال ابھی قابل جواب رہ جاتاہے اوروہ یہ ہے کہ ظاہر ی آسما ن پر سےجو شہب گرتے ہیں.ان کی کیاتوجیہہ ہے.آخر ان سے جو انبیاء کو مشابہت دی ہے.توضرور ہے کہ وہ بھی کوئی ایسافائدہ دیتے ہوں.جوشیطان پرچوٹ سمجھے جانے کے قابل ہو.نبیوں کے ظہور کے وقت دو قسم کے نشانات اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ نبیوں کے ظہور کے وقت وہ دو قسم کے نشان دکھاتاہے.ایک قسم کے نشان تو انسانوں کے قریب ہوتے ہیں.یعنی اس دنیاکی اشیاء میں ظاہر ہوتے ہیں.لیکن چونکہ بعض شکی مزاج لوگ ان کے متعلق خیا ل کرتے ہیں.کہ شاید نبی کی چالاکی یاہوشیاری کاان میں دخل ہو.وہ ایک دوسری قسم کے نشان بھی ظاہر کرتاہے.جو آسمانی اجرام سے تعلق رکھتے ہیں.انبیاء کے ظہور کے وقت شہب کے گرنے کا نشان ان میں سے ایک نشان ستاروں یعنی شہب کے ٹوٹنے کابھی ہے.جہاں تک تاریخی انبیاء کا تعلق ہے.حضرت مسیح ؑ ناصری اورآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ امر تاریخ سے ثابت ہے کہ اس وقت ستارے کثرت سے ٹوٹے تھے اوریہ نشان یاتواس نبی کی اپنی پیشگوئی کے ماتحت ظاہرہو تاہے یااس سے پہلے کے نبیوں یاولیوں کی پیشگوئیوں کے ماتحت ہوتاہے.آنحضرت ؐ کے زمانہ میں شہب بکثرت گرے چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی شہب کثرت سے گرے.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تواس کثرت سے گرے کہ کفارنے خیال کیا کہ شاید آسمان و زمین تباہ ہونے لگے ہیں.اور اہل سماء
Page 253
ہلاک ہو گئے ہیں.چنانچہ ابن کثیر نے بہ حوالہ لکھا ہے.کہ فَلَمَّابَعَثَ اللہُ مُحَمَّدًا صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم نَبِیًّا رَسُوْلًا رُجِـمُوْالَیْلَۃً مِنَ اللَّیَالِیْ فَفَزِعَ لِذٰلِکَ اَھْلُ الطَّائفِ فَقَالُوْا ھَلَکَ اَھْلُ السَّمَاءِ لَمَّا رَأوْ مِنْ شِدَّۃِ النَّارِ فِی السَّمَاءِ وَاخْتَلَافِ الشُّھُبِ فَـجَعَلُوْا یُعْتِقُوْنَ اَرِقَّاءُ ھُمْ وَیُسَیِّبُوْنَ مَواشِیَھُمْ فَقَالَ لَہُمْ عَبْدُ یَالِیْل بْنُ عَمْرِوبْنِ عُمَیْرٍ وَیْحَکُمْ یَامَعْشَرَاَھْلِ الطَّائِفِ اَمْسِکُوْاعَنْ اَمْوَالِکُمْ وَانْظُرُوْااِلٰی مَعَالِمِ النُّجُوْمِ فَاِنْ رَأیْتُمُوْ ھَا مُسْتَقِرَّۃً فِی اَمْکِنَتِہَا فَلَمْ یَھلِکْ اَھْلُ السَّمَاءِ اِنَّمَا ھٰذَا مِنْ اَجْلِ ابْن اَبِیْ کَبْشَۃَ یَعنِیْ مُحَمَّدًا صَلّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَ اِنْ نَظَرْتُمْ فَلَمْ تَرَوْھَا فَقَدْ ھَلَکَ اَھْلُ السَّمَاءِ فَنَظَرُوْا فَرَأَوْھَافکفُّواعَنْ اَمْوَالِھِمْ(ابن کثیر تفسیر سورئہ الجن زیر آیت انا لمسنا السماء) یعنے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بناکر مبعوث فرمایا.تو ایک رات شیطانوں پر سخت سنگ باری ہوئی (یعنےشہب گرے)تواسے دیکھ کر طائف کے لوگ سخت گھبراگئے اورآسمان پر بار بار اورکثر ت سے شہب کے ٹوٹنے کا نظارہ دیکھ کر کہنے لگے کہ معلوم ہوتاہے آسمان کے باشندے ہلاک ہوگئے ہیں.اس گھبراہٹ میں انہوں نے اپنے غلام آزادکرنے شروع کردیئے اورجانوروں کی رسیاںکھول کر انہیں کھلا چھوڑدیا.اس پر ان کے سردار عبدیالیل نے کہا کہ اے طائف کے لوگو!تمہارابراحال ہو اپنے مالوںکو سنبھال کر رکھواورآنکھیں اُٹھا کر ستاروں کودیکھو.اگر وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں تومعلوم ہواستارے نہیں ٹوٹ رہے شہب گررہے ہیں اورآسمان کے ساکن ہلاک نہیں ہوئے.بلکہ یہ نشان ابن ابی کبشہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم)کے لئے دکھایاگیاہے.اوراگر تم دیکھو کہ ستارے آسمان پر اپنی جگہوں پر نہیں ہیں توسمجھو کہ آسمان کے لوگ ہلاک ہوگئے ہیں (اورقیامت آگئی ہے )اس پر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا.توستاروں کو اپنی جگہ پر پایا اوراپنے اموال لٹانے بند کردیئے.آنحضرت ؐ کے وقت بعض آسمانی تغیرات کی انبیاء بنی اسرائیل سے خبر یہ نشان سابق پیشگوئیوں کے مطابق ظاہرہواتھا.چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتاہے کہ بعض آسمانی تغیرات کی انبیاء بنی اسرائیل نے زمانہ نبویؐ کے وقت کے متعلق خبر دی تھی.بخاری میں ہے.اِنَّ ھِرَقْلَ حِیْنَ قَدِمَ اِیْلِیَاءَ اَصْبَحَ یوْمًاخَبِیْثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِہِ قَدْ اَنْکَرْنَا ھَیْئَتَکَ.قَالَ ابْنُ النَّاطُوْرِوَکَانَ ھِرَقْلُ حَزَّاءً یَنْظُرُ فِی النُّجُوْمِ فَقَالَ لَہُمْ حِیْنَ سَأَلُوْہُ اِنّی نَظَرْتُ اللَّیْلَۃَ حِیْن نَظَرْتُ فِی النُّجُوْمِ اَنَّ مَلِکِ الخِتَانِ قَدْ ظَھَرَ.( بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ..) یعنی ہرقل زمانہ نبوی ؐ میں دورہ کرتے ہو ئے ایلیاکے مقام پر آیا.تو ایک دن صبح کے وقت اس کی طبیعت پریشان تھی.اس پر کلیسیائی جرنیلو ںمیں سے ایک نے پوچھا
Page 254
کہ آج آپ کی طبیعت کچھ پریشان معلوم ہوتی ہے.ابن ناطورکہتاہے کہ یہ ہرقل علم ہیئت کاماہرتھا اور رصدگاہوں میں بیٹھ کر ستاروں کو دیکھاکرتاتھا.اس نے اس سوال کایہ جواب دیاکہ جب آج رات میں ستاروں کامعائنہ کررہاتھا.میں نے وہ علامات دیکھیں جن سے معلوم ہوتاہے کہ عربوں کابادشاہ (یعنی نبی ؐ آخر الزمان) ظاہر ہوگیاہے ا س لئے پریشانی ہے.اوپر کے حوالوں سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ میں شہب غیر معمولی طور پر زیاد ہ گرے تھے اوراسی طرح بعض دوسری علامات آسمان میں ظاہر ہوئی تھیں.جوآپ کی آمد کا نشان تھیں اورجیساکہ بعض اور احادیث سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی شہب کثرت سے گرے تھے.(مجمع البحار) مسیح کی آمد ثانی کے وقت شہب گرنے کی پیشگوئی انجیل میں بھی مسیح کی دوبارہ آمدکے متعلق لکھا ہے ’’سورج اور چاند اورستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے‘‘(لوقاباب۲۱.آیت ۲۵)پس یہ امر واقعات اوراحادیث سے ثابت ہے کہ نبی کے ظہو ر کی علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شہب کاگرنا سنت کے طور پر مقرر کررکھاہے اس کی ظاہری وجہ توجیساکہ میں اوپر بتاچکاہوں یہ ہے کہ تااس آسمانی نشان کو دیکھ کرلوگ اس وسوسہ سے نجات پائیں کہ شاید اس کے معجزات کسی انسانی تدبیر کانتیجہ ہو تے ہوں.مگرکوئی تعجب نہیں کہ اس کے علاو ہ بھی کوئی مخفی وجہ نبی کے زمانہ میں شہب کے گرنے کی ہو.اوراس میں کوئی روحانی تاثیرات بھی ہوں.جو گوانسانی نگاہ سے مخفی ہوں.لیکن ان شیطانی تدابیر کاازالہ کرنے میںممد ہوتی ہوں.جوانبیاء کے دشمن کرتے رہتے ہیں.قرآن مجید میں مختلف مواقع پر آسمانوں کی حفاظت اور شہب گرنے کا ذکر ا س کے بعد میں ان مختلف آیات اوران کی تفاسیر کو لیتاہوں جو مفسرین نے کی ہیں.شہب گرنے کا ذکر سورۃ صافات ،جن اور حم سجدۃ میں قرآن کریم میں آسمان سے شہب یاپتھر پڑنے کا ذکر یاآسمانوں کی حفاظت کا ذکر مندرجہ ذیل سورتوں میں ہے (۱)سورئہ حجر زیر تفسیرآیت (۲)سورئہ مُلک (ع۱) اس میں آتاہے وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ جَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ (الملک:۶) ہم نے سماء دنیا کو ستاروں سے مزیّن کیاہے اورانہیں شیطانوں کو ماربھگانے کاذریعہ بنایا ہے (۳)سورئہ صٰفّٰت (ع۱)اس میں ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ا۟لْكَوَاكِبِ.وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ.لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ.اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ(۷ تا ۱۱).ہم نے ورلے آسمان کوستاروں سے مزیّن کیاہے اورہرباغی شیطان سے اسے محفوظ بنایاہے وہ ملاء اعلیٰ کی بات نہیں سن سکتے اورہر طرف
Page 255
سے انہیں بھگانے کے لئے ان پر پتھرائو ہوتاہے اوراس کے علاوہ بھی انہیں قائم رہنے والا عذاب ملے گا(وہ سن تو نہیں سکتے )لیکن اگر کوئی بات اچک لے جائے.تواس کے پیچھے چمکتاہواشہاب جاتاہے (اوراسے تباہ کردیتاہے ) (۴)سورئہ جنّ میں ہے.وَّ اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا.وَّ اَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ١ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا.(الجن : ۹،۱۰) اورہم نے آسمان کے بارہ میں جستجو کی ہے اوریہ معلوم کیا ہے.کہ اس میں سخت پہرہ لگاہواہے.اورشہب بھی مقرر ہیں.اوراس سے پہلے تو ہم آسمان میں سننے کی جگہوں پر بیٹھاکرتے تھے.مگر اب جو سننے لگتاہے وہ اپنے پر ایک شہاب کو نگران پاتاہے (۵)حٰم سجدہ میں ہے وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ١ۖۗ وَ حِفْظًا١ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ(حم السجدۃ:۱۳)اورہم نے ورلے آسمان کو چراغوں سے مزیّن کیا ہے.اوران کو ذریعہ حفاظت بھی بنایا ہے.یہ غالب اورعلم والے خدا کی تقدیرہے.شہب گرنے کے متعلق مختلف مفسرین کا بیان یہ پانچ مقام ہیںجن میں اس مضمون کو تفصیلاً یااجمالاً بیان کیاگیاہے.مفسرین اس کی حقیقت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی وحی ملائکہ پر نازل کرتاہے تووہ درجہ بدرجہ نیچے اترتی ہے جب سماء الدنیا تک پہنچتی ہے توجنّ ایک دوسرے پر چڑھ کر آسمان تک پہنچتے ہیں اوراس خبرکو اُڑانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ خبریں اُچک اُچکا کر جب وہ دوڑتے ہیں.توان کے پیچھے شہب مارے جاتے ہیں اس کے آگے اختلاف ہے.حضر ت ابن عباس ؓکی طرف یہ روایت منسوب کی جاتی ہے.کہ شہب شیطانوں کو مارنہیں سکتے.بلکہ زخمی کردیتے ہیں یابعض عضو توڑ ڈالتے ہیں لیکن حسن بصریؒ اورایک اورگروہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ شیطان قتل کردیئے جاتے ہیں.جوکہتے ہیں کہ شیطان قتل کردیئے جاتے ہیں وہ آگے پھر مختلف الخیال ہیں.ایک گروہ کہتاہے کہ جب وہ ساحروں اورکاہنوں کوخبر پہنچالیتے ہیں توپھر ماردیئے جاتے ہیں اورماوردی کاقول یہ ہے کہ خبرپہنچانے سے پہلے ہی شہب ان کو جاپکڑتے ہیں اورماردیتے ہیں.(فتح البیان زیر آیت ھٰذا) پھر مفسرین نے یہ بحث بھی کی ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شہاب پھینکے جاتے تھے اکثروں نے توکہا ہے.کہ ہاں پہلے بھی پھینکے جاتے تھے.مگر بعض کہتے ہیں کہ نہیں.آپؐ کی بعثت سے پہلے (یعنی زمانہ فترۃ میں)نہیں پھینکے جاتے تھے.دوسر ے خیال کے ظاہر کرنے والوںمیں علامہ زجاج بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی علامت تھی.آپؐ کی بعثت سے پہلے شہب نہ گرتے تھے ورنہ شعراء کے کلام میں اس کا ذکر ہوتا.مؤلف فتح البیان لکھتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو شہب کثرت سے گرے تاکہ غیب کی حفاظت اچھی طرح کی جاوے اورآپؐ کی بعثت سے پہلے کم گرتے
Page 256
تھے.تودونوں اقوال میں تطابق ہو سکتا ہے.(فتح البیان زیر آیت ھٰذا) درمنثور میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ(درمنثورسورئہ جن زیر آیت اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ )بیان ہواہے.کہ شیطان آسمان کی باتیں سناکرتے تھے جوسنتے اس میں سوجھوٹ ملا دیاکرتے تھے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو وہ اس سے روکے گئے.اس پر انہوں نے ابلیس سے ذکرکیا.اس نے تحقیق کے لئے ایک وفد بھجوایا.اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جَبَلَیْ نخلۃ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا.اورابلیس کو خبر دی.اس نے کہا بس یہی سبب مار پڑنے کاہے.بعض روایات میں ہے کہ ابلیس نے زمین کی مٹی منگوائی.اورسونگھ کر کہا کہ تہامہ کی زمین میں نبی ظاہر ہواہے.شہب کےگرنے والی آیات کی تفاسیر میں مفسرین کی بد احتیاطی افسوس کہ ان بزرگ مفسرین نے جنہوں نے قرآنی تفسیر کے بیان کر نے میں نہایت محنت اورکوشش سے کام کیا ہے اس معاملہ میں سخت بے احتیاطی برتی ہے اورغیر معروف روایات کے رعب میں آگئے ہیں.حالانکہ وہ قرآن کریم کے صریح خلاف ہیں.ان روایات سے معلوم ہوتاہے کہ(۱)شیطان آسمان کی باتوں کو سن لیتے تھے (۲)ان خبروں میں غیب بھی ہوتاتھا(۳)ابلیس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ان شہب کی مار پیٹ سے ہوئی پہلے نہ تھی.ان آیات کی تفاسیر کے تین غلط اصول ان تفاسیر کے یہ تین بنیادی اصول ہیں.ان تینوں باتوں کونکال دیاجائے.توروایات میں کچھ رہتاہی نہیں.لیکن یہ تینوں باتیں کیسی غلط ہیں.پہلی بات کہ شیطان آسمان سے باتیں سن سکتے ہیں.قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات کے خلاف ہے (۱)سورہ طور میں ہے.اَمْ لَہُمْ سُلَّمٌ یَّسْتَمِعُوْنَ فِیْہِ فَلْیَاْتِ مُسْتَمِعُھُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ(طور:۳۹) یعنی کیا آسمان کی بات سننے کے لئے ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعہ سے یہ آسمان پر جاکر خدا تعالیٰ کی بات سن لیتے ہیں؟ (یعنے ایساہرگز نہیں )اگر ان میں سے کوئی اس امر کامدعی ہے تووہ سامنے آئے اوراپنی دلیل پیش کرے.شیطان آسمان سے باتیں نہیں سنتے اس آیت سے صا ف ظاہر ہے کہ آسما ن پر جاکر بات سننا تو الگ رہا وہاں تک جانے کی قابلیت بھی کفار اور ان کے مددگاروں میں تسلیم نہیں کی گئی.اگریہ درست ہوتا کہ جنّ ایک دوسرے پر چڑھ کر آسما ن تک جاپہنچتے تھے.توکیاکفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب نہ دیتے.کہ ایک طرف آپ اس امر کے قائل ہیں کہ جنّ ایک دوسر ے پر چڑھ کر آسمان تک جاپہنچتے ہیں.اوردوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں.کہ آسمان تک جانے کی ان کے پاس کون سی سیڑھی موجود ہے.شیطانوں و جنوں کو غیبی امور معلوم ہوجانے کے متعلق قرآن مجید کا بیان (۲)سورئہ شعراء میں ہے
Page 257
وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ.وَ مَا يَنْۢبَغِيْ لَهُمْ وَ مَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠.اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ۠(الشعراء :۲۱۱.۲۱۳)یعنے کفار کا یہ الزام کہ اس شخص پر شیطان کلام نازل کرتاہے درست نہیں.کیونکہ(الف)اس کااپنا چال چلن ایسا اعلیٰ اورپاکیز ہ ہے.کہ ایسے آدمیوں سے شیطان کو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا.(ب)جو تعلیم اس پر نازل ہوئی ہے وہ ایسی مطہّر اور پا ک ہے کہ ناپاک شیطان اس تعلیم کو اُتارہی نہیں سکتا.کس طرح ممکن ہے کہ شیطان خود اپنے خلاف تعلیم اُتارے.(ج) اس میں آسمانی علوم ہیں اور شیطان آسمانی علوم کے سُننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے.کیونکہ خدا تعالیٰ نے انہیں آسمان کی باتیں سننے سے محروم کیا ہو اہے.ان زبردست قرآنی دلائل کی موجودگی میں یہ خیا ل کیونکر کیا جا سکتا ہے کہ شیطان آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں.دوسرا دعویٰ ان روایات میں یہ کیا گیا ہے.کہ شیطانوں یا جنّوں کو بعض غیبی امور بھی معلوم ہو جاتے تھے اور وہ زبردستی اخبار غیبیہ کو اچک لیتے تھے.یہ دعویٰ بھی مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ سے بالبداہت غلط ثابت ہوتا ہے.(۱) فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا١ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ(یونس: ۲۱) غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے (اگر وہ غیب تم کو ملے گا تو تم سچے مجھے ملے گا تو میں سچا ) پس آؤ !دونوں خدائی فیصلہ کا انتظار کریں.اس آیت کے ہوتے ہوئے کس طرح کہا جاسکتا ہے.کہ قرآن کریم کے رُو سے جنّات غیب کا علم آسمان سے اُچک لیتے تھے.(۲) سورہ طور میں ہے.اَمْ عِنْدَ ھُمُ الْغَیْبُ فَھُمْ یَکْتُبُوْنَ (طور:۴۲) کیا ان کے پاس غیب معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہے.جس سے غیب معلوم کر کے وہ لکھ لیتے ہیں ؟ یعنے ایسا ہرگز نہیں ہے (۳) یہی آیت سورئہ قلم میں بھی ہے (۴) سورئہ سباء میں ہے.وَّ قَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ١ۚ وَ يَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ.وَ حِيْلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ كَمَا فُعِلَ بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ١ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ.(سبا:۵۴،۵۵) یعنے یہ لوگ تیر ا انکار شروع سے کرتے چلے آئے ہیں.اور غیب کے امور کے دریافت کرنے کے لئے دُور سے بیٹھے ہوئے ڈھکونسلے مارتے رہے ہیں.مگر کامیاب نہیں ہوسکے ان کی غیب دانی کی خواہش کے راستہ میں اللہ تعالیٰ نے روکیں پیدا کررکھی ہیں جس طرح ان لوگوں کی خواہش کو پورا کرنے میں جوان سے پہلے گزر چکے ہیں روکیں پیدا کررکھی تھیں.اور یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں (ایسے لوگوں کو غیب مل ہی کب سکتاہے.یعنی غیب تو اس قلب پر نازل ہوتا ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہو) اور یقین اور ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہو.اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ وہ آسمان پر نہ جاتے تھے.بلکہ دور بیٹھے ڈھکونسلے مارا کرتے تھے.غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے (۵)وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ
Page 258
بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا١ؕ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ.(الانعام: ۱۱۳) یعنے جس طرح تیرے زمانہ میں ہورہاہے.اسی طرح ہم نے ہر نبی کے زمانہ میں انسان شیطانوں اورجن شیطانوں کو چھوڑ رکھاتھا.کہ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے جھوٹی باتیں سناتے تھے.اوراگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ بھی نہ کرسکتے.(مگر اس کی مشیت یہی ہے)اس لئے تو انہیں ان کے حا ل پر چھوڑ دے اور ان کے افترائوں کی طرف توجہ ہی نہ کر.اس آیت سے ظاہر ہے کہ انبیا ء کے دشمن جنّ و انس ایک دوسرے کو غیب کی باتیں نہیں بتاتے بلکہ جھوٹ بتاتے ہیں.آیت کے آخر میں بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آسما ن کی باتیں سنتے ہیں.تو ان سے الگ رہ.بلکہ یہ فرمایا ہے.کہ یہ افتراء کرتے ہیں.اس لئے تو ان سے الگ رہ.اس افترا ء کا جواب خدا تعالیٰ ہی دے گا.غیب کا اظہار اللہ تعالیٰ صرف رسولوں پر کرتا ہے (۶)عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا.اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا.لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَ اَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا(الجنّ :۲۷.۲۹) یعنے اللہ تعالیٰ غیب کاجاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب کو سوائے اپنے رسولوں کے جو اس کے منتخب ہوتے ہیں اور کسی پر ظاہرنہیں کرتا.پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس رسول کے آگے اورپیچھے نگران اورپہرہ دار چلتے ہیں.تاکہ اسے یہ علم بھی حاصل ہوجائے.کہ ان رسولوں نے اپنے رب کی بات لوگوں تک پہنچا دی ہے.اوران کے تما م امور کا وہ احاطہ کئے رکھتاہے اورہراک چیز کی تعد اد بھی اس کے پاس محفوظ رہتی ہے.یعنے کمیّت اور کیفیت دونوں کاریکارڈ اس کے پاس ہوتاہے کسی چیز میں کمی بیشی کاہوناممکن نہیں.یہ آیت کس وضاحت سے مذکورہ بالا تفاسیر کو باطل کرتی ہے فرماتا ہے نہ صرف یہ کہ غیب کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے.بلکہ اس غیب کا پہلا اظہار صرف رسولوں پرہوتاہے.رسول بھی وہ جن کو اللہ تعالیٰ خود منتخب فرماتا ہے نہ بندوں کے چُنے ہوئے رسول.پھر فرماتا ہے کہ جب تک وہ کلام رسول تک پہنچ نہ جائے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں تااس میں کوئی دوسرادخل نہ د ے سکے.جب رسولوں تک وہ کلام پہنچ جاتاہے.توپھر بھی اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں چھوڑتا.بلکہ حفاظت کرتارہتاہے یہا ں تک کہ و ہ رسول اس کلام کو بندو ں تک پہنچادیں اوراس طر ح مکمل طور پر پہنچادیں.کہ اس کی کمیت اورکیفیت دونوں میں کوئی فرق نہ آئے.جب تک رسول لوگوں تک کلام پہنچا نہ لیں شیطان کو اس کا علم ہی نہیں ہو سکتا گویا جب تک رسول لوگوں تک خدا تعالیٰ کاکلام پہنچا نہ دیں.اس وقت تک شیطان کو اس کلام کے متعلق کوئی علم ہی نہیں ہوسکتا.ہاں! جب وہ انسانوں میں پھیل جاتاہے توجیساکہ دوسری آیات سے ثابت ہے.شیطان اس کلام کے بارہ میں شرارتیں
Page 259
شروع کرتا ہے.مگر پھر بھی وہ ناکام رہتاہے.غرض اس آیت سے ثابت ہے کہ شیطان کاکلام الٰہی کو اچکنے کاکام کلام الٰہی کے اعلان کے بعد شروع ہوتا ہے.اوراس بارہ میں سماء الدنیا سے مراد نبی کی مجلس ہے.نہ کہ وہ فضا ء یا جَوّ جو ہمیں اپنے سروں کے اوپر نظرآتاہے.نہ رسول کریم صلعم کے وقت نہ اس سے پہلے کبھی جنوں کو غیب کا علم ہوا (۷)یہ تو عام آیات تھیں.ایک آیت خاص جنّوں کے متعلق بھی ہے.جس سے ظاہر ہے کہ نہ رسول کریمﷺ کے وقت میں نہ اس سے پہلے کبھی بھی جنّوں کو غیب کا علم حاصل ہواہے نہ پورا نہ ادھورا.اور وہ آیت یہ ہے.فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ١ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ.(سبا:۱۵) یعنے جب حضرت سلیمان پر ہم نے موت وارد کی تو ان کی موت کا علم جنّوں کو اس وقت تک نہ ہو سکا.جب تک کہ دابۃ الْارض نے جو ان کے عصا کو کھارہا تھا انہیں خبر نہ دی پھر جب وہ گر گئے تو جنّوں نے یہ امر معلوم کر لیا.کہ اگر انہیں غیب کا کچھ بھی علم ہوتا تو وہ اس ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے.اس آیت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم ﷺ سے پہلے زمانہ میں بھی جنّوں کو غیب کا علم حاصل نہ تھا.اگر وہ آسمان پر سے سنا کرتے ہوتے تو انہیں حضرت سلیمان کی وفات کا علم کیوں حاصل نہ ہوتا.یہ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان چونکہ نبی تھے.ان کی وفات کی خبر ضرور الہاماًاور خاص اہتمام سے فرشتوں پر نازل ہوئی ہوگی.کیونکہ نبی کی بعثت اور موت دونوں اہم امور ہوتے ہیں.تفاسیر کا یہ دعویٰ کہ جنوں کو رسول کریم صلعم کی بعثت کا علم شہب کے گرنے سے ہوا غلط ہے تیسر ا دعویٰ تفاسیر میںیہ کیا گیا ہے کہ جنّوںکو بلکہ ابلیس کو رسول کریم ﷺ کی بعثت کا علم آسمانی شہب کے بعد ہوا ہے اور وہ بھی جب کہ رسول کریم ﷺ کو باجماعت نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا.جیسا کہ تاریخوں سے ثابت ہے.رسول کریم ﷺ نے نماز با جماعت پبلک میں کئی سال بعد شروع کی ہے(سیرۃ النبی لابن ہشام باب اسلام عمر بن الخطاب ).پس اگر یہ معنے درست ہیں.تو اس کے یہ معنے ہوںگے.کہ رسول کریم ﷺ کی بعثت کے کئی سال بعد تک ابلیس کو یہ معلوم ہی نہ تھا.کہ کوئی رسول مبعوث ہو اہے.حالانکہ یہ صریح تعلیم قرآن کے خلاف ہے اور واقعہ کے خلاف ہے.نبی کی بعثت پر شیطان کے گھر میں ماتم نبی کے دعویٰ کے ساتھ ہی شیطان کے گھر میں ماتم پڑجاتا ہے اور اسی وقت سب شیطان خواہ شیاطین الانس ہوں.خواہ شیاطین الجنّ ہوں.اس کی اور اس کی جماعت کی مخالفت
Page 260
شروع کردیتے ہیں.پس یہ کہنا.کہ کئی سال تک ابلیس کو اور دوسرے شیاطین کو اس کا علم ہی نہ تھا.کہ رسول کریم ﷺ مبعوث ہوچکے ہیں.سنت الٰہیہ کا ردّ ہے اور واقعات کے خلاف.اگر شیطان کوآپؐ کی بعثت کا علم نہ تھا.تو مکہ میں مخالفت کا طوفان بے تمیزی کہاں سے اٹھ رہا تھا.ابلیس کے کوئی بھی معنی کرو.اس کا نبی کریم ﷺ کی بعثت سے ناواقف رہنا خلاف عقل.خلاف قرآن اور خلاف سنت الٰہیہ ہے.قرآن کریم صاف فرماتا ہے.وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا.(الانعام :۱۱۳) شیٰطین الانس و الجن کو نبی کی بعثت کا علم فوراً ہو جاتا ہے جس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود شیاطین الانس والجنّ کو نبیوں کی بعثت کا علم مناسب ذرائع سے دے دیتا ہے اور وہ نبی کی بعثت کے معاً بعد اُس کی مخالفت شروع کردیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد شروع کردیتے ہیں پھر ابلیس یا اس کے چیلوں کا اس خبر سے ناواقف رہنا کیا معنے رکھتا ہے یاد رہے کہ اس مضمون میں بغرض سہولت اور حجت ابلیس یا جن وغیرہ کے الفاظ کے متداول معنے میںنے لئے ہیں اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے.کہ میرے نزدیک وہی معنی درست ہیں.اس کی بحث اپنے موقعہ پر آئے گی کہ میرے نزدیک ابلیس شیطان یا جنّ کے کیا معنے ہیں ؟ جنوں کا ایک دوسرے پر چڑھ کر غیب کا حاصل کرنے کا مطلب اس جگہ ایک سوال رہ جاتا ہے.کہ جب غیب کا علم آسمان سے لینا یا آسمان سے خبروں کا سننا جنّوں کے لئے ناممکن ہے تو پھر حدیثوں میںجو آتا ہے کہ جنّ ایک دوسرے پر چڑھ کر آسمان کی خبر سنتے ہیں.اس کا کیا مطلب ہوا ؟اس کا جواب یہ ہے.کہ اس سے مراد انبیا ء کی باتوں کو سننا ہے اور ایک دوسرے پر چڑھ کر سننے سے یہ مراد ہے.کہ آئمۃ الکفر خود انبیا ء کی مجالس میں حاضر نہیںہوتے اور براہ راست اپنے دلوں کے شکوک کو دُور نہیں کرواتے.بلکہ ہمیشہ کئی واسطوں اور بزعم خود ہوشیاری سے ان کی تبلیغ اور تعلیم کو معلوم کرتے ہیں.پھر چونکہ اوّل تو اُن کی اپنی نیّت خراب ہوتی ہے.دوسرے وہ سنی سنائی باتوں پر اپنی مخالفت کی بنیاد رکھتے ہیں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قدر جھوٹ ان کے بیان میں مل جاتا ہے کہ ایک بات سچی ہو تو سوجُھوٹی ہوتی ہیں.شیطانوں پر شہاب گرنے سے مراد اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ کبھی شیطان لوگوں تک بات پہنچا دیتے ہیں.اور پھر شہاب ان پر گرتا ہے.اور کبھی بات پہنچانے سے پہلے شہاب ان پر گرجاتا ہے.اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ نبیوں پر گستاخی کرنے کے جرم میں فوراً پکڑے جاتے ہیں.اور بعض کو حکمت الٰہی لمبی مہلت دے دیتی ہے.اور وہ لوگوں کو خوب بھڑکاتے رہتے ہیں.یہاں تک کہ ایک دن شہاب ان کو بھی آکر پکڑ لیتا ہے.
Page 261
شیطانوں پر شہب کے گرنے کا دو حدیثوں میں ذکر میں اس جگہ دو حدیثیں بھی درج کردیتا ہوں تاکہ اصل الفاظ حدیث کے بھی مستحضر رہیں.ایک روایت بخاری کی ہے جو یہ ہے… عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَیَبْلُغُ بِہِ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ قَالَ اِذَا قَضَی اللّٰہُ الْاَمْرَ فِی السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَا ئِکَۃُ بِاَجْنِحَتِہَا خُضْعَانًا لِقَوْلِہِ کَالسِّلْسِلَۃِ عَلٰی صَفْوَانٍ قَالَ عَلِیٌّ وَقَالَ غَیْرُہُ صَفْوَانٍ یَنْفُذُھُمْ ذٰلِکَ فَاِذَافُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِھِمْ قَالُوْا مَاذَاقَالَ رَبُّکُمْ قَالُوْا للِّذِیْ قَالَ الْحَقُّ وَھُوَ الْعَلِّیُّ الْکَبِیْرُ فَیَسْمَعُہَا مُسْتَرِقُوْالِسَّمْعِ وَ مُسْتَرِقُوْ السَّمْعِ ھٰکَذَاوَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ سُفْیَانُ بِیَدِہِ وَفَرَّجَ بَیْنَ اَصَابِــعِ یَدِہِ الیُمْنَی نَصَبَھَا بَعْضَہَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرُبَّمَا اَدْرَکَ الشِّہَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ اَنْ یَرْمِیَ بِھَا اِلٰی صَاحِبِہِ فَیُحْرِقَہُ وَرُبَّمَا لَمْ یُدْرِکْہُ حَتّٰی یَرْمِیَ بِہَااِلَی الَّذِیْ یَلِیْہِ اِلَی الَّذِی ھُوَاَسْفَلَ مِنْہُ حَتّٰی یُلْقُوْھَا اِلَی الْاَرْضِ وَ رُبَّمَا قَالَ سُفْیَانُ حَتّٰی تَنْتَھِیَ اِلَی الْاَرْضِ فَتُلْقَی عَلَی فَمِ السَّاحِرِ فَیَکْذِبُ مَعَہَامِائَۃَ کَذْبَۃٍ فَیُصَدَّقُ فَیَقُوْلُوْنَ اَلَمْ یُخْبِرْنَا یَوْمَ کَذَاوَکَذَا یَکُوْنُ کَذَاوَکَذَافَوَجَدْنَا ہُ حَقًّا لِلْکَلِمَۃِ الَّتِیْ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ(بخاری کتاب التفسیر سورۃ الحجر باب قولہ الا من استرق السمع)دوسری روایت ابن ابی حاتم کی ہے.جو یہ ہے.قَالَ اِبْنُ اَبِی حَاتِمٍ…عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ اِذَا اَرَادَ اللہُ تَبَارَکَ وَتَعَالیٰ اَنْ یُّوْحِیَ بِاَمْرِہِ تَکلَّمَ بِالْوَحْیِ فَاِذَاتَکَلَّمَ اَخَذَتِ السَّمٰوٰتُ مِنْہُ رَجْفَۃً اَوَقَالَ رِعْدَۃٌ شَدِیْدَۃٌ مِنْ خَوْفِ اللہِ تَعَالیٰ فَاِذَاسَمِعَ بِذَالِکَ اَھْلُ السَّمٰوٰتِ صَعِقُوْا وَخَرُّوْ ا لِلہِ سُجَّدًا فَیَکُوْنُ اَوَّلُ مَنْ یَرْفَعُ رَأْسَہُ جِبْرِیْل عَلَیْہِ الصَّلوٰۃُ وَالسَّلَامُ فَیُکَلِّمُہُ اللہُ مِنْ وَحْیِہِ بِمَا اَرَادَفَیَمْضِی بِہٖ جِبْرِیْلُ عَلَیْہ الصّلوٰۃُ وَالسَّلَامُ عَلَی الْمَلٰئِکَۃِ فَکُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَمَاءً یَسْأَلُہُ مَلَائِکَتُھَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا یَاجِبْرِیْلُ فَیَقُوْلُ عَلَیْہِ السَّلَامُ قَالَ الْحَقُّ وَھُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیْرُ.فَیَقُوْلُوْنَ کُلُّھُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِیْلُ فَیَنْتَھِیْ جِبْرِیلُ بِالْوَحْیِ اِلٰی حَیْثُ اَمَرَہُ اللہُ تَعَالیٰ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ (تفسیر ابن کثیر سورۃ الحجر).ابن ابی حاتم کی اس روایت سے معلوم ہوتاہے کہ وحی جبریل کی حفاظت میں اس مقام تک پہنچادی جاتی ہے جو وحی کے لئے مقرر ہے یعنے رسول تک.پس دوسری روایات جو بتاتی ہیں.کہ جنّ اسے چک لیتے ہیں.ان کے یہی معنے ہوسکتے ہیں کہ مورد وحی کے پاس جب وحی پہنچ جاتی ہے.اورجب و ہ اس کا اعلان کردیتاہے.اس کے بعد شیطان اُسے اچکتے ہیں.اور کئی جھو ٹ ملا کر انہیں اپنے اتباع میں پھیلادیتے ہیں.نبیو ں کی باتیں اس زمانہ کے
Page 262
لوگوں کے لئے عجیب توہوتی ہی ہیں پہلے تولو گ حیران ہوتے ہیںکہ کیا یہ مدعی ایسی ایسی باتیں کرتاہے؟مگر کبھی نبی کے اتباع سے جب وہ اس حصہ کو سنتے ہیں جو شیطانوں نے صحیح بیان کیا تھا.توا ن کے اتباع یقین کرلیتے ہیں.کہ جو دوسری باتیں انہوں نے بیان کی تھیں.وہ بھی صحیح تھیں.اورآپس میں کہتے ہیں کہ دیکھا فلاں بزرگ نے فلاں د ن ان کے بارہ میں یہ با ت کہی تھی.وہ درست نکلی.اس مدعی کے مرید خود اس کی تصدیق کرتے ہیں.پس اس سے ان کو ان جھوٹوں پر بھی یقین آجاتاہے.جو ان کے سرداروں نے نبیوں کی طرف منسوب کئے ہوئے ہوتے ہیں.وہ سمجھتے ہیں.کہ نبی کے اتباع ان باتوںکو ہم سے چھپاتے ہیں.اصل بات وہی ہے جو ہمارے لیڈروں نے کہی تھی.یہ ایک عجیب سلسلہ ہے جو ہرنبی کے وقت میں چلتاہے اورلاکھو ںآدمی جو اپنی تحقیق کامدار اپنے لیڈروںکے بیانات پر رکھتے ہیں.اورذاتی تحقیق کی زحمت گوارانہیں کرتے.ا س بلا میں گرفتار ہو کر صداقت سے محروم رہ جاتے ہیں.ان آیات کے متعلق جو معانی عوام میں مشہور ہیں.یابعض مفسرین نے صحیح روایات کا مفہوم غلط سمجھنے کی وجہ سے یاکمزورروایات کوصحیح تسلیم کرلینے کی وجہ سے قرآن کریم کے منشاء کے خلاف لکھے ہیں.ان کے متعلق بعض اورغور طلب امور بیان کرکے میں اس تعلیق کو ختم کرتاہوں.گرنے والے وجود سے مراد ستارے نہیں بلکہ شہب ہیں گرنے والے وجود سے مراد ستارے نہیں بلکہ شُہب ہیں.پس وہ معترضین جو کہتے ہیں کہ گویا قرآن کریم کے نزدیک آسمان سے گرتی ہو ئی نظر آنے والی روشنی حقیقی ستار ے ہوتے ہیں.درست نہیں.نہ یہ بات قرآن کریم میں ہے نہ اس کے معتبر مفسر یہ معنے کرتے ہیں.بلکہ مفسرین توالگ رہے کفار تک بھی اس امر کو سمجھتے تھے.کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی علامت یہ نہ تھی کہ ستارے ٹوٹیں بلکہ یہ تھی کہ شُہب گریں.(جیسا کہ اوپر طائف والوں کاواقعہ بیان ہوچکاہے.) آسمان کے محفوظ ہونے کے باعث شیطان وہاں سے کوئی بات نہیں اچک سکتے قرآن کریم میں متواتر یہ بیان ہواہے کہ ہم نے آسمان کی حفاظت کی ہے.پس جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس سے شیطان کس طرح کو ئی بات اُچک سکتے ہیں.جب سماء دنیا تک کلام اُتر آتاہے.اورشیطان وہاں سے اسے اُچک لیتے ہیں.توسوال یہ ہے کہ کیا فرشتے اس کلام کو نبی پر جلدی اتارتے ہیں.یا شیطان اپنے اولیا ء پر.اگر فرشتے پہلے اُتاردیتے ہیں.توشیطانوں کو آسمان سے اُچکنے کاکیافائد ہ ہوا.نبی کے منہ سے اس خبر کودنیا پہلے ہی سن چکی ہو گی.اوراگر یہ کہا جائے.کہ فرشتے نبی تک دیر میں پہنچتے ہیں شیطان اپنے اولیا ء تک جلد پہنچ جاتے ہیں.توسارے خدائی سلسلہ پر اعتراض ہوگا.اگر باوجود
Page 263
اس قدر حفاظت کے جواللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے.شیطان کلام کے پہنچنے سے پہلے ہی اسے اچک لیتے ہیں توپھر نبیوںکے کلام پر کیا اعتباررہا.جس طرح شیطان اسے اچک سکتے ہیں اس میں کچھ ملابھی سکتے ہیں (گو بعض لوگوں نے اس خیال کا بھی اظہارکیا ہے کہ شیطان نبی کی زبان پر بھی بعض کلمات جاری کردیتاہے.العیاذ باللّٰہ)(تفسیر ابن کثیر زیر آیت وما ارسلنک من قبلک من رسول.) اگریہ ممکن ہے کہ شیطا ن باوجو د حفاظت کے خدائی کلام کو اُچک لیتے ہیں.تب تو یہ بھی کہاجاسکتاہے کہ ممکن ہے.خدا تعالیٰ کی حفاظت کے باوجود وہ نبی کو ہلا ک بھی کردیں نعو ذ باللہ من ذالک.مگر جس طرح یہ نہیں ہوسکتا.اسی طرح یہ بھی نہیں ہوسکتا.کہ کلام الٰہی کو شیطا ن اُچک کر لے جائے.بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ یا اِلَّامَنْ خَطِفَ الْخَطْفَۃَ فرما کر خود ہی فرما دیا ہے کہ شیطان کچھ سن لیتا ہے یااچک لیتا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ اِلَّا اللہ تعالیٰ کے فعل کے بارہ میں نہیں.بلکہ شیطان کے بارہ میں ہے.اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتاکہ ہم اپنے کلام کی حفاظت کرتے ہیں.سوائے کچھ تھوڑے سے کلام کے جو ہم شیطان کو دے دیتے ہیں.تب تو یہ جوا ب صحیح ہوتاکہ خدا تعالیٰ کی طاقت پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے دیتاہے.لیکن عبارت یو ں نہیں.عبارت تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ توحفاظت کرتاہے لیکن شیطان اچک لے جاتا ہے اور یہ معنی نہ صرف نبی اور کلام الٰہی کی شان کے خلاف ہیں بلکہ ان سے تونعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی بے بسی اور بے کسی بھی ظاہر ہوتی ہے.اگر یہ معنے درست ہوں.توچاہیے کہ جب کو ئی نجومی حساب لگائے اورکوئی زائچہ تجویز کرے.اسی وقت شُہب آسمان سے گرنے لگیں.مگریہ نہیں ہوتا.پس واقعات ان معنوں کو ردّ کر رہے ہیں.رات دن ہزاروں نجومی.کاہن.رمّال.جفّار.جوتشی.پنڈت.سٹرانومر.سٹارلو جر ان کاموں میں مشغول ہیں اورغیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں.اگر ان لوگوں کا تعلق شیطانوں سے ہے اورشیطان آسمان سے اچک کر انہیں خبریں بتاتے ہیں.تورات اوردن شہب کی بارش ہوتی رہنی چاہیے.اگر کہا جائے کہ شہب اسی وقت گرتے ہیں.جبکہ شیاطین باتیں سنیں.تواس کے معنی یہ ہوں گے.کہ نبیوں کے زمانہ میں شیطان زیادہ باتیں سنتے ہیں اوراچک کر لے جاتے ہیں.حالانکہ نبی کا زمانہ تو زیادہ محفو ظ زمانہ ہوتاہے.اورہونا چاہیے.پھر سوال یہ ہے.کہ یہ امتیاز کیونکر کیاجائے.کہ نبی کے زمانہ میں تونجومی شیطانوں سے خبریں سن کر لوگوںکو سناتے ہیں اور دوسرے زمانہ میں صرف حسا ب لگاکر سنادیتے ہیں؟کیونکہ دونوں قسم کی خبرو ں میں کوئی فرق کرناپڑے گا.یاتو یہ کہنا ہوگا.کہ نبی کے
Page 264
زمانہ میں نجومیوں کی باتیں زیادہ سچی ہوتی ہیں.جو بالبداہت غلط ہے یاپھر ماننا پڑے گا.کہ ہر زمانہ میں ہی نجومی شیطانوں سے باتیں پوچھ کر آگے لوگوں کو سناتے ہیں اورجوشخص ستاروں کا تھوڑا ساعلم بھی جانتا ہو.وہ بتاسکتاہے کہ یہ خلاف عقل بات ہے.علم نجوم و رمل وغیرہ گو لغو اورفضول ہیں.مگر حسابی اصول پر قائم ہیں.جنّات کا اس معاملہ میں کوئی بھی دخل نہیں.ہاں ایک گروہ ہے.جو ارواح سے اپنا تعلق ظاہر کرتاہے اور وہ وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں انگریزی میں یہ لوگ سپر چولسٹ کہلاتے ہیں.ان لوگوں کا دعویٰ ہے.کہ وہ ارواح سے ملتے او رباتیں کرتے ہیں.ان کا ذکر بھی آیات مذکو ر ہ میں نہیں ہوسکتا.کیونکہ ان کے متعلق بھی ہم نہیں دیکھتے کہ اِدھر وہ حاضرا ت کاعمل کریں اوراُدھر شہب گر نے لگیں.اس نام نہاد علم کی طرف منسوب ہونے والے لو گ یا تو ٹھگی اورفریب کے مرتکب ہوتے ہیں او ران کی بھی کافی تعدا د ہے یاپھر وہ دھوکہ خوردہ لوگ ہیں جو انسانی دماغ کی باریکیوں کو نہ سمجھتے ہوئے بعض باریک روحانی قویٰ کو عالم اُخروی کی ارواح کا عمل اور تاثیر قرار دے لیتے ہیں.بہر حال نہ ان کی مزعومہ ارواح آسمان سے سنتی ہیں اورنہ ان پر شہاب گرتے ہیں.خلاصہ یہ کہ ان آیا ت میں کلام الٰہی کی حفاظت کا ذکر ہے اوراللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی پرکلام کے نازل ہونے تک کوئی اسے معلوم نہیں کرسکتا.جب وہ نازل ہو جاتا ہے تو پھر شیاطین الانس والجن اسے مختلف ذرائع سے اچک کر اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں او رنبی کے خلاف انہیں اکساتے ہیں.یہ ظاہر ہے کہ ایسے ہی موقع پر جھوٹ ملانے کافائدہ ہو سکتا ہے.ورنہ جنّ آسمان سے غیب سنیں تو وہ پاگل ہیں کہ اس میں جھوٹ ملا کر اپنی عزت کھوئیں.ہاں! نبی کے کلام میں ان کے دشمن جھوٹ ملاتے ہیں.تاکہ لوگوں کو جوش دلائیں اور ان کے خلاف اُکسائیں.کوئی صحیح حوالہ لیا.اس کے غلط معنے کئے یاایک ٹکڑہ لیا.اور سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کے مضمون سے لوگوں کو جوش دلایا.یہ نبیوں کے دشمنوں کا روزمرہ کامشغلہ ہے.اوریہی وہ اچکنا ہے.جسے اللہ تعالیٰ کی مشیت نے جائز رکھا ہے.اور اس سے نبی کے مشن کی حفاظت نہیں کی.شیطانوں کو کلام الٰہی کے غلط معانی پھیلانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی بناء پر دے رکھی ہے بلکہ فرماتا ہے.کہ ہم دشمنوں کو ا سکاخود موقع دیتے ہیں جیسے خود فرمایا وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا (الانعام :۱۱۳) اور فرماتا ہے.وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا (الانعام :۱۲۴) اور اسی طرح ہم نے ہر(نبی کی )بستی میں اس کے بڑے
Page 265
مجرموں کو ایسا ہی بنادیا ہے.(اس کا ذکر پہلی آیت میں آیا ہے.کہ شیطان اپنے دوستوں کوالہام کرتے او رنبی کے خلاف جھگڑنے کے لئے اُکساتے ہیں )اس کانتیجہ یہ ہوتاہے کہ وہ نبی کے خلاف خوب تدبیریں کرتے ہیں.غرض جہاں کلام الٰہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حفاظت حاصل ہے.کہ اس میں کوئی ظاہری یا باطنی دشمن تبدیلی نہیں کرسکتا.وہاں اللہ تعالیٰ نے شیطانی لوگوںکو اپنی مصلحت سے اس امر کی اجازت دے رکھی ہے.کہ اس کلام کے غلط معنے لوگوں میں پھیلائیں.یانبی کی وحی کے متعلق جھوٹ بو ل بول کر لوگوںکو جوش دلائیں.لیکن جب وہ ایسا کرچکتے ہیں توپھر ان پر آسمان سے شہا ب گرتا ہے.او ر نبی کے ذریعہ سے ان کے فریب کا پردہ چاک کردیاجاتاہے.یہ وہ استثناء ہے کہ اس سے نہ خدا تعالیٰ کی طاقت پر حرف آتا ہے نہ دین مخدوش ہوتا ہے.کیونکہ اس قسم کی شرارت کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی مستثنیٰ کردیا ہواہے.نیز اس قسم کی شرارت سے دین میں کچھ حرج نہیں آتا.وہ اپنی جگہ محفوظ رہتاہے.یہ جھوٹی باتیں صرف دشمنوں میں پھیلائی جاتی ہیں اوردشمن کی چند روزہ خوشی کاموجب ہوتی ہیں.کلام الٰہی کے خلاف شرارتیں کرنے والے دو قسم کے لوگ یہ بھی یادرکھناچاہیے کہ قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتاہے.کہ کلام الٰہی کے خلا ف اس قسم کی شرارتیں کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں.ایک اندرونی دشمن یعنی منافق.اورایک بیرونی دشمن.اس کا ثبوت اس امر سے ملتاہے کہ سورئہ حجر اورسورئہ ملک میں تو شیطان رجیم کی طرف اس فعل کو منسوب کیا گیا ہے.اورسورئہ صافات میں شَیْطانٍ مَارِد کی طرف.اورلغت میں جہاں رجیم کے معنے دھتکارے ہوئے دور رکھے گئے کے ہیں مَارِد کے معنی باغی کے ہیں.پس سورئہ حجر اورسورئہ ملک میں ان دشمنانِ دین کا ذکر ہے جو کفار میں سے ہوں.یعنی جن کو ظاہر میں بھی اسلام کے قریب آنے کی توفیق نہ ملی ہو.بلکہ وہ اس سے دور رکھے گئے ہوں اوربتایاہے کہ ان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کرے گا.اورسورئہ صافات میں یہ بتایاہے کہ بعض لوگ مسلمان کہلاتے ہوئے بھی نادانستہ یا شرارتاً قرآنی مطالب کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کریں گے.وہ شیطان ماردٍ ہوں گے.یعنے ظاہر میں تو مسلمان کہلائیں گے لیکن درحقیقت اسلام کے دانستہ یا نادانستہ باغی ہوں گے ان کے فساد کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا.یہ آئندہ کے لئے پیشگوئی ہے او ر بتایا ہے.کہ جب بھی مسلما ن قرآنی مطالب کے سمجھنے سے قاصر ہوجائیں گے اوراس کے مطالب کو بگاڑ دیں گے.اللہ تعالیٰ مامور مبعوث کر کے ان کے شرا ور فتنہ سے قرآن کریم کو محفوظ کرے گا.فَتَبَارَکَ اللہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ.ایک بات او ربھی یاد رکھنے کے قابل ہے او روہ منجمین اورنام نہاد روحانیین کے بارہ میں ہے.انبیاء کاوجود
Page 266
ان کے خیالات کاقلع قمع بھی کرتا رہتا ہے پس ضمنی طور پر ان کے متعلق بھی یہ آیت چسپاں ہوسکتی ہے مگر خود علم نجوم یا تاثیرات نجوم کاتعلق جہاں تک حقائق سے ہے.یہ ہر گز اسلام کے خلاف نہیں.قرآن کریم ہمیں قوانین نیچر کے سیکھنے کاخود حکم دیتا ہے.پس یہ ناممکن ہے کہ ایک طرف تو وہ علم ہیئت میں حکمتیں رکھے.ان کے سیکھنے کاحکم دے اورپھر جو ان حکمتوں کو سیکھنا چاہے.اس پر شہب مارے جائیں.اسلام وہم او رشرک سے روکتا ہے.پس جہاں تک ان علوم کا تعلق تخمین اوروہم سے ہے وہ ناجائزہیں اورجب ان کو مذہب کی طرح سمجھاجاتا ہے.وہ شرک بن جاتے ہیں ستاروں کی حرکات میں تاثیرات یقیناً ہیں لیکن وہ قانون قدرت کا ایک جز و ہیں.ہزاروں امور ایک وقت میں تاثیر ڈال رہے ہوتے ہیں.اپنی ذات میں کامل تاثیر جو دوسرے کی محتاج نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہے.ستاروں کی قطعی تاثیر کا خیال رکھنے والا مشرک ہے پس ستارے کیا کسی اور مادی سبب کے متعلق بھی اگر کوئی شخص خیال کرے کہ وہ قطعی اوریقینی تاثیر رکھتا ہے توو ہ مشرک ہے.اسی وجہ سےرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَنْ قاَلَ مُطِرْنَا بِنَوءِ کَذَاوَکَذَافَھُوَ کافرٌ بی وَمومنٌ بالکوکبِ جو کہے فلاں فلاں ستار ہ کی تاثیر کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی وہ کافر ہے (بخار ی کتاب الاذان باب یستـقبل الامام الناس اذا سلم )ستارو ں کی تاثیرات میں اول تو سینکڑوں وہمی باتیں شامل کردی گئی ہیں لیکن جو علمی طورپر ثابت ہیں و ہ بھی ہزاروں اسبا ب میں سے ایک سبب ہے مسبب الاسباب خداان کانگران اور موکل ہے پس اسی پر توکل چاہیے.نجومیوں کے لحاظ سے رجم شیاطین کے معنے نجومیوں وغیرہ کے لحاظ سے اس رجم شیاطین کے یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ جس زمانہ میں نبی نہیں ہوتے.یہ لوگ خوب دعویٰ کرتے رہتے ہیں.لیکن جب نبی ظاہرہوتے ہیں تو ان کو خوب مار پڑتی ہے یعنی فریب کھل جاتاہے.اورلوگ مصّفیٰ علم غیب اور تُک بندی میں فرق معلوم کرلیتے ہیں.وَ الْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَ اَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا اور(ضرور) ہم نے زمین کو پھیلایاہے او راس میں ہم نے محکم پہاڑ قائم کئے ہیں اور(نیز)ہم نے اس میں ہرقسم کی مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ۰۰۲۰ موزون(ومناسب) چیزوںکو (پیدا کیااور)بڑھایاہے.حل لغا ت.وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰھَا وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰھَا زمین میں ہم نے کھاد ڈالی ہے.یاہم نے
Page 267
اس کو پھیلایاہے.مزید تشریح کے لئے دیکھو سورۃ رعد آیت نمبر ۴.مَوْزُوْنٌ وَزَنَ سے اسم فاعل ہے.اوروَزَنَہُ.وَزَنًاکے معنے ہیں رَازَثِقَلَہُ وخِفَّتَہُ وَامْتَحَنَہُ بِمَا یُعَادِ لُہُ کہ کسی چیز کے بھاری اورہلکے ہونے کا اندازہ کیا.اوراس کے بالمقابل وزن کی چیز سے اس کے وزن کا اندازہ معلوم کیا (جیسے بٹّوں سے تولتے ہیں )وَفِی الْاَسَاسِ’’وَزَنْتُ الشَّیْءَ وَرَزَنْتُہُ وَثَقَلْتُہُ اِذَارُزْتَہُ بِیَدِکَ لِتَعْرِفَ وَزَنَہُ ‘‘اوراساس میں یوں لکھا ہے.کہ وَزَنَ.رَزَنَ اورثَقَلَ ہم معنے ہیں.اوران کے معنے ہیں کہ کسی چیز کو ہاتھ میں لے کر اس کے وزن کا اندازہ کیاجائے.اور وَزَنَ تَمْـرَ النَّخْلَۃِ وزْنًا کے معنے ہیں.خَرَصَہُ وَحَزَرَہُ کھجور کے پھل کی مقدار کا اندازہ کیا.(اقرب) پس موزون کے معنے ہوں گے اندازہ کی ہوئی چیز.وزن کی ہوئی چیز یامتناسب.تفسیر.زمین کو پھیلانے اور اس میں کھاد ڈالنے کا مطلب زمین کو ہم نے پھیلایاہے یااس میں کھاد ڈالی ہے.دونوں معنے ہی اس آیت میں چسپاںہوتے ہیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرور ت کے مطابق پھیلایا ہے یعنی ا س قدر وسیع بنایاہے کہ باوجود گول ہونے کے وہ انسان کے لئے تکلیف دہ نہیں.بلکہ اس کی گولائی کو وہ محسوس بھی نہیں کرتا اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس میں کھاد ڈالی ہے کیونکہ زمین نئی نئی طاقتیں دوسرے ستاروں سے حاصل کرتی رہتی ہے.بلکہ علم ہئیت سے ثابت ہے کہ دوسرے سیاروں سے ذرات زمین پر گرتے رہتے ہیں اوراس کا حجم بڑا ہورہا ہے.وہ بیرونی کھاد اس کی طاقت کو بہت بڑھاتی رہتی ہے.کھاد کے بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے سو اس کے متعلق فرمایا.کہ ہم نے اس میں پہاڑ بنائے ہیں.جو برفوںکو سمیٹ کر رکھتے ہیں اورپانیوں کاذخیرہ ان کے ذریعہ موجود رہتا ہے اوردریائوں کی مدد سے سب دنیا میں پھیل کر اسے سیراب کرتاہے.اَنْبَتَ کے دو معنی ا س کے بعد فرماتا ہے.ہم نے ہر مناسب شے مناسب مقدار میں اُگائی یابڑھائی ہے اَنْبَتَ نَبَاتًا (یعنے اُگانا)زمین سے کسی چیز کو بطریقہ نشوونمانکالنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.لیکن محاورہ میں اس کے معنی بڑھانے کے بھی آتے ہیں.مثلا ً قرآن کریم میں حضرت مریم ؑ کے متعلق آتا ہے.وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا(آل عمران :۳۸) اس جگہ یہ لفظ بڑھانے اورترقی دینے کے معنوں میں استعمال ہواہے.اس آیت میں انبت کےدونوں معنی چسپاں ہوتے ہیں آیت زیر بحث میں یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہواہے.اوراَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ کے معنے ہیں ہم نے زمین میں ہرمناسب چیز پیداکررکھی ہے.یااسے ترقی دے رہے ہیں.یاہرچیز جس کا ایک اندازہ لگایاگیاہے اُسے اُگایا.یااسے ترقی دی ہے.
Page 268
یعنی ہر چیز جو اہل دنیا کی ضرورتوں کو پوراکرنے والی تھی وہ ہم نے اس میں رکھ دی اوروز ن کے معنے اندازہ کے بھی ہیں.تواس لحاظ سے یہ معنے ہوں گے کہ ہر چیز اندازے کے مطابق ا س میں رکھ دی گئی ہے.اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے کہ کس چیز کی اس میں ضرورت ہے اورکتنی ضرورت ہے.اس نے کمیت اورکیفیت دونوں کو ملحوظ رکھا ہے.اس آیت کا پہلی آیتوں سے تعلق اس آیت کا تعلق پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں قرآن کریم کے نزول اوراس کی حفاظت کے غیر معمولی سامانوں کا ذکر تھا.جو ایک آسمانی مثال سے ثابت کیا گیا تھا.زمین کے نشو نما پانے اور اس کو کمزوری سے بچانے کے لئے تین سامان اب زمین کی مثال دی کہ زمین میں بھی ہم نے اس کے نشوونماپا نے اورا سکے کمزوری سے بچانے کے لئے غیر معمولی سامان پیداکررکھے ہیں کچھ بیرونی ہوتے ہیں کچھ اندرونی.(۱)آسمان سے گرنے والا مادہ(۲)پہاڑ(۳)اس کی اندرونی طاقتیں.یہی حال الٰہی کتاب کا ہوتا ہے.وہ آسمان سے مدد پاتی رہتی ہے اس کی تائید میں ائمہ لگے رہتے ہیں اوروہ اپنے اندر ذاتی خوبیاں رکھتی ہے.جن کی وجہ سے اس کے مطالب ہر طبقہ کے لوگوں کے لئے جاذب رہتے ہیں.وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَ مَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ اوراس میں ہم نے تمہارے لئے اور(ہر)اس (مخلوق)کے لئے (بھی)جسے تم رزق نہیں دیتے معیشت کے بِرٰزِقِيْنَ۰۰۲۱ سامان پیداکئے ہیں.حلّ لُغَات.مَعَایِش.مَعَایِش مَعِیْشَۃٌ کی جمع ہے.اورمَعِیْشَۃٌ کے معنے ہیں.اَلَّتِیْ تَعِیْشُ بِھَا مِنَ الْمَطْعَمِ وَالْمشْرَبِ.وہ کھانا او رپیناجس سے انسان زندہ رہتاہے.وَمَا تَکُوْنُ بِہِ الْحَیَاۃُ جس پر زندگی کادارومدار ہو.وَمَا یُعَاشُ بِہِ مِنْ طَعَامٍ وَنَحْوِہِ مِمَّا یُکْسَبُ.کھانااوراس جیسی اورضروریات جن کو انسان کما کر حاصل کرتا ہے.اس پر بھی معیشت کالفظ بولاجاتا ہے.اَوْیُعَاشُ فِیْہِ مِنْ مَکَانٍ وَزَمَانٍ وہ وقت یا جگہ جس میں زندگی بسر کی جائے.(اقرب) تفسیر.زمین میں تمہارے لئے ہر قسم کے سامان پیداکئے گئے ہیں.اوران کارز ق بھی پیدا کیاگیا ہے
Page 269
جن کو تم رزق نہیں دے سکتے.انسان دوسرے حیوانوں پر برتری کا دعویدار ہے.لیکن رزق جمع کرنے میں کس قدر تکلیف اٹھاتاہے.لیکن اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ہزارکیڑوں مکوڑوں کارزق کس طرح مہیاکررکھا ہے.انسان تو ان کو رزق نہیں دیتا.مگر پھر بھی سب کو رزق مل رہاہے.یہ ایک بالا ہستی کاثبوت ہے جس کی نظر سے اس کی کوئی مخلوق پوشیدہ نہیں.اوپر کی آیات سے ا س آیت کا یہ بھی تعلق ہے کہ روحانی غذائوں کا بھی انسان ہرزمانہ میں محتاج ہوتا ہے.ایک زمانہ کے لوگ دوسرے زمانہ کے لوگوں کے لئے صحیح روحانی غذامہیا نہیں کرسکتے.اس لئے انسانی علوم بدلتے رہتے ہیں.اس لئے فرمایا کہ ایسے وسیع مطالب والے الہامی کلام کی جو آسمان سے نازل ہو اوراسے محفوظ رکھا جائے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ اگر انسانوں پر معاملہ چھوڑ دیاجائے.توآئندہ نسلوں کاوہ کبھی خیال نہ رکھیں.اپنے زمانہ کے حالات اورعلوم کے مطابق کلام الٰہی کو ڈھا ل لیں اور اگلے لوگ حیران و پریشان رہ جائیں.گذشتہ علوم ان کی تسلی کاموجب نہ ہو ں.اورنئی ضرورتوں کو کلام الٰہی پورانہ کرتا ہو.پھر وہ کیا کریں؟ا س لئے فرمایا.کہ جس طرح ان جانداروں کا رزق ہم نے مہیا کیا ہے.جن کو تم رزق نہیں دے سکتے یا نہیںدیتے.اسی طرح ان انسانوں کے لئے ہم نے اس کلام میں ذخیرہ جمع کررکھا ہے.جو بعد میں آنے والے ہیں.اورپہلے زمانہ کے لو گ ان کی روحانی غذاکا انتظام نہیں کرسکتے.جب وہ وقت آئے گااللہ تعالیٰ ان خزانوں کو ان کے لئے کھول دے گا.اور وہ روحانی غذا حاصل کرلیں گے.اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے.اگر قرآن کریم کے علوم گذشتہ زمانہ تک محدود ہوتے.توآج روحانی غذاکے طالبوں کے لئے سخت مشکلات ہوتیں.اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ویسا ہی وسیع بنایا ہے جیسے مادی دنیا کو مگر اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ویسا ہی وسیع بنایا ہے.جیسا کہ مادی دنیا کو بلکہ اس سے زیادہ اورہر زمانہ کے مطابق اس میں سےعلوم نکلتے رہتے ہیں.وَ اِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآىِٕنُهٗ١ٞ وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا اورکوئی چیز ایسی نہیںجس کے (غیر محدود)خزانے ہمارے پاس نہ ہو ں او ر اسے ہم ایک معیّن اندازے سے بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ۰۰۲۲ ہی اُتارتے ہیں.حلّ لُغَات.نُنَزِّل.نُنَزِّلُ نَزَّلَ سے مضارع جمع متکلم کاصیغہ ہے.اور نَزَّ لَہُ کے معنے ہیں.صیَّرَہُ
Page 270
نَازِلًا اس کو اترنے والا کردیا.یعنی ایسی حالت میں کردیا کہ اُترے.القومَ.اَنْزَلَھُمُ الْمَنَازِلَ.لوگوں کو ان کی جگہوں پر اتارا.الشَّیْءَ.رَتَّبَہُ.کسی چیز کو مرتب کیا.عِیْرَہُ.قَدَّرَلَھَا الْمَنَازِلَ.قافلہ کے امام نے قافلہ کے لوگوں کے لئے جگہیں مقرر کردیں (اقرب) تَنزیل اصل میں آہستہ آہستہ اتارنے کو کہتے ہیں.اَلْقَدَرُ.اَلْقَدَرُ مَایُقَدِّرُہُ اللہُ مِنَ الْقَضَاءِ.وہ قضا جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتاہے.وعَرَفَہُ بَعْضُہُمْ بِاَنَّہُ تَعَلُّقُ الْاِرَادَۃِ بِالْاَشْیَائِ فِیْ اَوْقَاتِھَا.اوربعض نے قدرکی یہ تعریف کی ہے کہ اشیا ء کااپنے اوقات پر وقوع پذیر ہونا قدر کہلاتاہے.مَبْلَغُ الشَّیءِ کسی چیز کی حد اورانتہاء.الطَّاقَۃُ.طاقت.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں ایک بہت بڑی صداقت بیان کی گئی ہے.اورپہلی آیت کی مزید تفصیل کی گئی ہے ہرچیز کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں.اورضرورت کے مطابق وہ انسانی ذہن کو ادھر منتقل کردیتاہے.اورلوگ ان خزانوں سے فائدہ اٹھالیتے ہیں.زمین میں سبھی کچھ تھا.مگر ایک وقت تک انسان نے لوہے کاعلم حاصل نہ کیاتھا.پھر لوہانکلا.اوراسے لوگوں نے خوب استعمال کیا.مگر لوہابے جان تھا.جب انسان کی ضرورت بڑھی اور اس نے دنیا میںکثرت سے پھرناچاہا.توپتھر کے کوئلے اوربھاپ کی دریافت ہوئی اوربے جان لوہا جانداروں کی طرح کام کرنے لگا.ضرورت نے ترقی کی.توتا ر کی بجلی کی ایجاد ہوئی.اس کے بعد بے تار کی بجلی کی.غرض ہرزمانہ کے مطابق زمین خزانے اگلتی چلی جاتی ہے.کلام الٰہی کے خزانے حسب ضرورت نازل کئے جاتے ہیں اسی طر ح فرماتا ہے.الٰہی کلام کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اس کے خزانے محفوظ رکھے جاتے ہیں اورزمانہ کی ضرورت کے مطابق نازل کئے جاتے ہیں.پس کلام الٰہی کو صرف ایک کتاب نہیں سمجھنا چاہیے کہ نازل ہوگئی اور پھر خدا تعالیٰ نے اس سے تعلق چھوڑ دیا.بلکہ کلام الٰہی ایک دنیا ہے جو ہزاروں خزانوں پر مشتمل ہے جو مختلف زمانہ کے لوگوں کے لئے ہیں جب تک وہ خزانہ سب کا سب مستحقین میں تقسیم نہ ہوجائے اس کلام کو بے حفاظت کس طرح چھوڑاجاسکتاہے.ہاںجس کلام کاخزانہ خالی ہوجائے چونکہ اس میں کوئی چیز پہنچانے والی نہیں رہتی اسے چھوڑ دیاجاتاہے.ان آیا ت میں مسلمانوں کو خطاب یاد رہے کہ پچھلی آیات میں گومضمون وہی حفاظت قرآن کا ہے لیکن ان میں مسلمانوں کوبھی خطاب میں شامل کرلیاگیاہے.اورحفاظت قرآن کے عقیدہ کے متعلق مسلما ن جن غلطیوںمیں پڑسکتے تھے.ان کا جواب بھی دیاگیاہے.
Page 271
وَ اَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً اورہم نے (بخارات کو)اُٹھانے والی ہوائیں (بھی تمہارے لئے )چھوڑ رکھی ہیں.اور(انکے ذریعہ سے )ہم نے فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ١ۚ وَ مَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ۰۰۲۳ بادلوں سے پانی اُتاراہے.پھر وہ تمہیں پینے کو دیاہے اور تم (خود) اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے.حلّ لُغَات.لَوَاقِحَ.لَوَاقِحَ یُقَالُ لَقِحَتِ النَّاقَۃُ لَقَاحًا وَکَذَالِکَ الشَّجَرۃُ.اونٹنی حاملہ ہوگئی اوردرخت ثمردار ہوگیا.وَاَلْقَحَ فُلَانٌ النَّخْلَ کھجور کے نرومادہ کو ملایا.وَاَرْسَلْنَاالرّیَاحَ لَوَاقِحَ اَیْ ذَوَاتِ لَقَاحٍ.یعنی لَوَاقح کے معنے ہیں.وہ ہوائیں جو درختوںسے نرکامادہ لے کر درختوں تک پہنچاتی ہیں (مفردات) اللَّوَاقِحُ مِنَ الرِّیَاحِ الَّتِیْ تَحْمِلُ النَّدَی ثُمَّ تَمُجُّہُ فِی السَّحَابِ فَاذَااجْتَمَعَ فِی السَّحَابِ صَارَ مَطَرًا.لَوَاقِح ان ہوائوں کو کہتے ہیں.جوزمین پر سے اُٹھنے والے بخارات کو لے کر چلتی ہیں.پھر بادلوں میں ان کو ملادیتی ہیں.(اقرب) تفسیر.لوَاقِح سے مراد لوَاقِح ان ہوائوں کو کہتے ہیں جو درختوں میں سے نرکامادہ لے کر درخت تک پہنچاتی ہیں.اوراس طرح درختوںکو پھل آتاہے.اسی طرح ان ہوائوں کوبھی لواقح کہتے ہیں جو زمین پر سے اُٹھنے والی رطوبت کو لے کر اُڑتی ہیں.یہاں تک کہ وہ بادلوں کی صورت اختیار کرلیتی ہیں.ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں لَوَاقِح سے مراد پانیوں کو جمع کرکے بادل بنانے والی ہوائیں ہوں.اوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی معنے اس جگہ مراد ہوں یعنے ہم وہ ہوائیں بھی چلاتے ہیں جو نردرختوں کامادہ مادہ درختوںپر ڈال کرانہیں پھل لانے کے قابل بناتی ہیں اوروہ ہوائیں بھی چلائی ہیں جو زمینی رطوبتوں کو جمع کرکے بادل کی صورت میں تبدیل کردیتی ہیں اورزمین پر بادلوںکو برساکر ان درختوںکو جو پہلی قسم کی ہوائوں کے ذریعہ سے نرومادہ کا میل کرچکے ہیں کثرت سے پھلدار بناتی ہیں آخر میں یہ بتایا کہ پانی کیسی ضروری شے ہے اور کبھی عام مگرانسان اسے بھی محفو ظ نہیں رکھ سکتا پھر روحانی امور میں وہ کیو نکر اپنے آپ کو محافظ کے مقام پر کھڑاکرنا چاہتاہے.کفار کے اس شبہ کا جواب کہ پہلی کتب کی موجودگی میں قرآن کریم کی کیا ضرورت ہے اس آیت میں حفاظت کلام الٰہی کے بارہ میں کفار اورمسلمانوں دونوں کو مخاطب کیاگیا ہے.کفار کے اس شبہ کا جواب دیاگیا ہے
Page 272
کہ پہلی کتب کی موجودگی میں قرآن کریم کی کیاضرور ت ہے؟ اوربتایا ہے کہ پانی کی موجودگی میں بادلوں کی ضرورت ہوتی ہے.بغیر آسمانی بارش کے زمینی پانی کام کانہیں رہتا.اس آیت سے مسلمانوں کو نصیحت اورمسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن کریم کی موجودگی سے مغرورنہ ہونا.آسمانی پانی آسمان ہی سے صاف ہوکر ملتاہے.جب کبھی تم لوگ اپنے خیالات کو ملا کر کلام الٰہی کے مطالب کو گنداکردوگے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسے سامان کرے گاکہ پھر قرآنی مطالب صاف ہو کر دنیا کو پہنچادیئے جائیں گے.وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ نَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ۰۰۲۴ اوریقیناً ہم ہی (ہرایک کو ) جِلاتے اورمارتے ہیں اورہم ہی (سب کے ) وارث ہیں حلّ لُغَات.اَلْوَارِثُ.اَلْوَارِثُ وَرِثَ سے اسم فاعل ہے.نیزالْوَارِثُ کے معنی ہیں.اَلْبَاقِیْ بَعْدَ فَنَائِ الْخَلْقِ.یعنی وارث کالفظ خدا تعالیٰ پرا س لحاظ سے بولتے ہیں کہ وہ مخلوق کے فنا ہونے کے بعدباقی رہے گا.وَفِی الدُّعَاءِ ’’اللّٰھُمَّ اَمْتِعْنِیْ بِسَمْعِیْ وَبَصَرِیْ وَاجْعَلْہُ الْوَارِثَ مِنِّی‘‘ اَیْ اِبْقِھِمَا مَعِیْ صَحِیْحَیْنِ حَتّٰی اَمُوْتَ.اورحدیث میں ایک دعاہےجس میں کان اورآنکھ کے لئے وارث کالفظ استعمال ہواہے.جس کے معنے ہیں کہ موت تک وہ صحیح سلامت رہیں.(اقرب) تفسیر.فرمایا ہم ہی باقی رہنے والے ہیں.تم جو فانی ہوبھلا کلام الٰہی کی کیسے حفاظت کرسکتے ہو.اس لئے ہم اپنا کلام بندوں کے سپرد نہیں کرسکتے.وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا اورہم تم میں سے آگے نکل جانے والوںکو(بھی )یقیناًجانتے ہیںاور(اسی طرح)ہم(تم میں سے)پیچھے رہ جانے الْمُسْتَاْخِرِيْنَ۰۰۲۵ والوں کو(بھی) یقیناً جانتے ہیں تفسیر.قرآن کریم کی حفاظت محض ظاہری علوم پر مبنی نہیں بلکہ قلبی طہارت سے تعلق رکھتی ہے یعنی یہ خیال نہ کرو کہ آخر مومن بندے دنیا میں موجود ہیں.وہ کیوں حفاظت کاکام نہیں کرسکتے.فرماتا
Page 273
ہے ایمان کا دل سے تعلق ہے.اور دل کے حالات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے.قرآن کریم کی حفاظت محض ظاہر ی علوم پر مبنی نہیں بلکہ قلبی طہارت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون نیکی میں بڑھا ہواہے اورکون نہیں.پس یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جسے وہ مستقدم دیکھے گااس کے سپرد یہ کام کرے گااورجو قلبی طہارت میں مستاخر ہوں گے خواہ ظاہری علوم میں کتنے ہی زیاد ہ کیوں نہ ہو ں وہ ا س کا م کے اہل نہ سمجھے جائیں گے.وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ١ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌؒ۰۰۲۶ اوریقیناً تیرار ب ہی انہیں جمع کرے گا وہ یقیناً حکمت والا (اور)بہت جاننے والا ہے حلّ لُغَات.یَحْشُرُ.یَحْشُرُحَشَرَ سے مضارع کاصیغہ ہے.اورحَشَرَ النَّاسَ کے معنے ہیں.جَمَعَہُمْ.لوگوں کو جمع کیا.وَیَوْمُ الْحَشْرِ.یَوْمُ الْبَعْثِ وَالْمَعَادِ وَھُوَ مَأْخُوْذٌ مِنْ حَشَرَ الْقَوْمَ اِذَا جَمَعَـہُمْ.اوریوم البعث کو یوم حشر انہی معنوں کی روسے کہتے ہیں کہ اس دن اگلے پچھلے لوگوںکو جمع کیا جائے گا.وَالْحَاشِرُ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَائِ نَبِیِّ الْمُسْلِمِیْنَ.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ایک نام حاشر بھی ہے.(اقرب) تفسیر.حشر کے معنے حشر کے معنے جمع کرنے کے ہیںاورحشر انہی معنوں کے روسے بعث مابعد الموت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے.کیونکہ اس دن اگلے پچھلے سب انسانوں کو جمع کیاجائے گا.حشر کالفظ اس اجتماع کے لئے بھی بولاجاتاہے جو نبیوںکے ذریعہ سے اس دنیا میں ہوتاہے یعنی ساری قوم کو اختلاف اورجھگڑے سے نکال کر وحدت کی رسی میں پرودیاجاتاہے.ہر نبی کے زمانہ میں حشر ہوا کوئی نبی نہیں آیا جس کے ذریعہ سے حشر نہ ہواہو.رسول کریم صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے زمانہ میں دیکھو کیسا حشر ہواکہ مختلف الخیال لو گوںکو ایک کلمہ پر جمع کردیاگیااورپھر ساری دنیا میں پھیلا دیاگیا.اس آیت میں دونوں حشرکی طرف اشارہ ہے.دنیوی حشر کی طرف اس طرح کہ گوآج تیری قوم تیرے خلاف ہے.لیکن ایک دن سب کو تیرے ہاتھ پر جمع کردیاجائے گا.حکیم و علیم کی صفات سے یہ بتایاہے کہ فوری طورپر اس لئے جمع نہیں کیاگیا کہ یہ حکمت کے خلاف ہے.فوراً لوگ اسی طرح جمع ہوسکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر تصرف کرکے انہیں جبر کے ذریعہ سے مسلمان بنادیتا مگر اس کا کیا فائدہ تھا وہ لوگ جو اس طرح مسلمان ہوتے کسی انعام
Page 274
کے مستحق نہ ہوتے.آنحضرت ؐ کے زمانہ میں حشر دوسرے ان لوگوں میں جو خاص روحانی طاقتیں رکھتے ہیں اورنبی کو اس کے شروع زمانہ میں پہچان لیتے ہیں ان میں اورکمزوروں میں کوئی امتیاز نہ رہتا اگر ایساہوتاتوابوبکرؓ اورابو جہل میں کیا فرق رہ جاتا.سب ہی ایک دم مسلمان ہوجاتے اوردنیا ابوبکرؓ کی قابلیتوں کو اورابو جہل کی نالائقیوں کو جان نہ سکتی.پس ایساکرنا حکمت کے خلاف تھا.اس لئے خدا تعالیٰ نے جبر سے کام نہیں لیا اوراس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قابل جوہروں اورناقص لوگوں اوربالکل ناقابل لوگوں کے حالات دنیا کو معلوم ہوگئے اور اس کے نتیجہ میں دنیا نے ابوبکرعمراورعثمان اورعلی رضوان اللہ علیھم سے اپنے اپنے وقت میں فائدہ اٹھایا.اگرسب ہی پہلے دن مسلمان ہوجاتے توممکن ہے پہلی سیادت کی وجہ سے لو گ ابوبکرؓ کی جگہ ابو جہل یاویسے ہی کسی آدمی کو اپنا سردار بناتے اوران فوائد سے محروم رہ جاتے جو ابوبکر وغیرہ سابق الایما ن صحابہؓ سے ان کو پہنچے.ھو یحشرھم میں علیم کہنے کی وجہ علیم کہہ کریہ بتایا کہ گو اس حکمت کی وجہ سے دیر ہوئی ہے مگر اس سے مایوس نہ ہوناچاہیے خد اجو علیم ہے تم کو بتاتا ہے کہ آگے چل کر سب عرب اس دین کے اصول پر جمع ہوجائے گا.اُخروی زندگی کے لحاظ سے یہ بتایاکہ ایک دن سب اگلے پچھلے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور جمع کئے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کی جزاپائیں گے.پس وہ ابتدائی تکالیف جو مسلمانوں کو پہنچ رہی ہیں ان کا خیال نہ کرنا چاہیے نہ ان لو گوں کو ناکام سمجھنا چاہیے جو اس شیطانی اور رحمانی جنگ میں فتح سے پہلے مارے جائیں گے کیونکہ اصل روزِجزا تو مرنے کے بعد آنے والا ہے اوراللہ تعالیٰ کی حکمت اورعلم نے اس دنیا کو اصل روزِجزا نہیں بنایا.وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ اورانسان کو ہم نے یقیناً آواز دینے والی مٹی سے یعنی سیاہ گارے سے جس کی ہئیت تبدیل ہوگئی تھی مَّسْنُوْنٍۚ۰۰۲۷ پیدا کیاہے.حلّ لُغَات.صَلْصَال: صَلْصَالٌ اسم ہے اس سے فعل ماضی صَلْصَلَ ہے.اورصَلْصَلَ الشَّیْءُ کے معنے ہیں صَوَّتَ.اس چیز نے آوازدی.صَلْصَلَ الْجَرْسُ.رَجَّعَ صَوْتُہُ.اوراگر صَلْصَلَ الْجَرْسُ کہیں تویہ
Page 275
معنی ہوں گے کہ گھنٹی میں سے سُردار (یعنی وہ جو ٹن کر کے لمبی آواز نکلتی ہے )آواز نکلی.صَلْصَلَ فُلَانًا.اَوْعَدَہُ وَھَدَّدَہُ.صَلْصَلَ فُلَانًا کے معنے ہیں کہ اس کو ڈرایا اوردھمکایاجب صَلَصَلَ زَیْدٌ کہیں.تواس کے معنے ہوں گے.قَتَلَ رَئِیْسَ الْعَسْکَرِ زید نے لشکر کے سردار کو قتل کیا (کیونکہ سردار کے قتل کرنے سے ایک شور پڑ جاتاہے ) صَلْصَلَ الرَّعْدُ.صَفَاصَوْتُہُ.بجلی کی آواز میں سریلی گونج پیداہوئی اورصَلْصَالَ کے معنے ہیں الطِّیْنُ الْحُرُّ خُلِطَ بِالرَّمْلِ وَقِیْلَ الطِّیْنُ مَالَمْ یُجْعَلْ خَزَفًا وہ مٹی جو خالص ہو اورا س کے ساتھ ریت ملی ہوئی ہو اوربعض کہتے ہیں کہ وہ مٹی جو پکائی نہ گئی ہو (اقرب).اورتاج العروس میں اس کے یہ معنے کئے گئے ہیں کہ صَلْصَلَ اللِّجَامُ وَکَذٰلِکَ کُلُّ یَابِسٍ یُصَلْصِلُ امْتَدَّ صَوْتُہُ کہ لگام سے سُردار آواز نکلی اورایسے ہی ہر خشک چیز سے جو سُر دارآواز پیداہو اسے صَلْصَالٌ کہتے ہیں.وَفِی رِوَایَۃٍ اَحْیَانًا یَأْتِیْنِیْ مِثْلَ صَلْصَلَۃِ الْجَرْسِ.ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاکبھی وحی مجھ پر اس طرح نازل ہوتی ہے جیسے گھنٹی کی لمبی آواز.وَالصَّلْصَالُ:الطِّیْنُ الحُرُّ خُلِطَ بِالرَّمْلِ فَصَارَ یَتَصَلْصَلُ اِذَاجَفَّ اورخالص مٹی جس میں ریت ملادی گئی ہو اسے صَلْصَال کہتے ہیں فَاِذَاطُبِخَ فِی النَّارِ فَھُوَ الفَخَّارُ.مگر اسے جب آگ میں پکایاجائے تواسے فخّار کہتے ہیں.وَقَالَ مُجَاھِدٌالصَّلْصَالُ حَمَأٌ مَسْنُوْنٌ.اورمجاہد نے کہا ہے کہ صلصال کے معنے سڑی ہوئی مٹی کے ہیں.وَصَلْصَلَ الرَّجُلُ.اَوْعَدَ وَتَھَدَّدَ اورصلصل کافعل جب کسی انسان کی طرف منسوب کریں تو معنے یہ ہوں گے کہ اس نے دھمکی دی.اورڈرایا.وَاَیْضًا اِذَاقَتَلَ سَیِّدَ الْعَسْکَرِ.یایہ کہ اس نے سردار لشکر کو قتل کردیا.وَتَصَلْصَلَ الْغَدِیْرُ اِذَاجَفَّتْ حَمْأَتُہُ.تَصَلْصَلَ الْغَدِیْرُ اس وقت کہتے ہیں کہ جب جوہڑ کا گاراخشک ہوجائے.وفرس صَلْصَالٌ.حَادُّالصَّوتِ دَقِیْقُہُ اورگھوڑے کو صلصال کہتے ہیں جب اس کی آواز تیز اورباریک ہو.وَقَالَ اَبُوْ اَحْمَدَ الْعَسْکَرِیُّ یُقَالُ لِلْحِمَارِالوَحْشِیِّ الْـحَادِّ الصَّوْتِ صَالٌّ وَصَلْصَالٌ.اورابواحمد عسکری نے کہا ہے کہ وہ گورخر جس کی آواز تیز ہواسے بھی صَالٌّ اور صَلْصَال کہتے ہیں.وَبِہِ فُسِّرَ الْحَدِیْثُ اَتُحِبُّوْنَ اَنْ تَکُوْنُوْ ا مِثْلَ الْحَمِیْرِ الصَّالَۃِ کَاَنّہُ یُرِیْدُ الصَّحِیْحَۃَ الْاَجْسَادِ الشَّدِیْدَ ۃَ الْاَصْوَاتِ لِقُوِّتِہَا وَنَشَاتِھَا اورانہی معنوں کی روسے اس حدیث کی تفسیر کی جاتی ہے.جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم چاہتے ہوکہ صالّہ گورخروں کی طرح ہو جائویعنی وہ جو اپنی مضبوطی اورقوت کی وجہ سے صحیح جسموں والے تیزآواز والے ہوتے ہیں ویسے تم بھی ہو جائو (تاج العروس).یہ روایت مجمع البحار میںبھی آئی ہے اورمجمع البحار میں یہ بھی لکھاہے کہ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ الصَّلْصَالُ ھُوَالْمَاءُ یَقَعُ عَلَی الْاَرْضِ فَتَنْشَقُّ فَیَجِفُّ وَیَصِیْرُلَہُ صَوْتٌ یعنی
Page 276
ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ صلصال اس پانی کو کہتے ہیں جو زمین پر گر کرخشک ہوجائے اوروہ مٹی جس پر وہ گرے خشک ہوکر آواز دینے لگے (خشک زمین کی پپڑیاں) وَالصَّلْصَالُ.الطِّیْنُ اَلْیَابِسُ یَصِلُّ اَیْ یُصَوِّتُ عِنْدَ النَّقْرِ اَوِ الْمُنْتِنُ(مجمع البحار زیر مادہ صلل).صلصال اس خشک مٹی کو کہتے ہیں جو ٹھکرانے پر آواز دیوے اسی طرح سڑی ہوئی مٹی کو بھی کہتے ہیں.حَمَأٌ:حَمَأَ یَحْمَأُ الْبِئْرَ.نَزَعَ حَمْاَتَھَا حَمْاَالْبِئْرَ کے معنے ہیں کنوئیں میں سے گارا نکالا.اَلْحَمَأُ کُلُّ مَاکَانَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ مِثْلَ الْاَخِ وَالاَبِ اورحَمأخاوند کی طرف سے رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں جیسے خاوند کابھائی یاباپ وغیرہ ہما.اَلْحَمَأُ:الطِّیْنُ الْاَسْوَدُ اورحمأ کالی مٹی کو بھی کہتے ہیں.(اقرب) مَسْنُونٍ:مَسْنُوْنُ سَنَّ یَسُنُّ سَنًّاسے اسم مفعول ہے اورسَنَّ السِّکّینَ کے معنے ہیں اَحَدَّہُ چھر ی کو تیز کیا.وَھٰذَامِمّایَسُنُّکَ عَلَی الطَّعَامِ ایْ یَشْحَذُکَ عَلٰی أَکْلِہِ وَیُشَھِّیہِ اِلَیْکَ یعنی یہ چیز ان چیزوں میں سے ہے جو تجھے کھانے کے لئے تیار کردے گی اوراس کی تجھے رغبت دلائے گی.سَنَّ الطِّیْنَ.عَمَلَہُ فخَّارًا اور سَنَّ الطِّیْنَ کے معنے ہیں کہ مٹی کو پکاکر سخت کردیا.سَنَّ الشَّیْءَ :سَھّلَہُ کسی چیز کو آسان کردیا.صَوَّرہُ یا اس کی شکل بنادی.سَنَّ عَلَی الْقَوْمِ سُنَّۃً.وَضَعَہَا کوئی طریق مقرر کیا (اسی سے لفظ مسنون نکلا ہے کہ جس کامفہوم یہ ہوتاہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے یہ طریق مقرر کیا ہے )اورمسنون کے معنے ہیں.المُنْتِنُ یعنی بدبودار چیز اَلْمَسْنُوْنَۃُ الْاَرْضُ الَّتِیْ اُکِلَ نَبَاتُھَا اورایسی زمین کو بھی جس کاگھاس ختم ہوچکا ہو مسنون کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ میں من کے متعلق اختلاف اس آیت میں یہ جو فرمایا ہے مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ.اس کے بارہ میں مفسرین میں اختلاف ہے کہ مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ میں مِنْ کے کیا معنے ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہ اپنے مجرورکے ساتھ مل کر صفت ہے.صَلصَال یعنی وہ صلصال جو حَمَائٍ سے بنا ہے (ابوالبقاء.کشاف زیر آیت ھذا)بعض نے کہا ہے کہ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ بدل ہے من صلصال کا (بحر محیط لأبی حیان و املاء ما من بہ الرحمن لابی البقاء) اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہصلصال سے ہماری مراد حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ہے.گویا پہلی ترکیب کے لحاظ سے تو اس کے یہ معنے ہیں کہ انسان کی پہلی حالت حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ کی تھی پھر اس سے صلصال بنا.اوردوسری ترکیب کے لحاظ سے یہ معنے ہوںگے کہ صلصال اورحَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ سے ایک ہی حالت کی طرف اشارہ کرنامطلوب ہے.صرف مضمون کی وضاحت کے لئے دوہم معنی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں.
Page 277
میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بدل کے معنوں کی صورت میں مِنْحمائٍ مسنون کو عطف بیان قراردینا زیادہ صحیح ہے کیونکہ بدل میں مقصود دوسر ااسم ہوتاہے.اورپہلا اسم اس کے مفہوم کو قریب کرنے کے لئے لایاجاتاہے.اورعطف بیان میں مقصود اسم اول ہوتاہے اوردوسرا اسم اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے لایاجاتاہے.اوراس آیت میں میرے نزدیک پہلا جملہ یعنی من صلصالٍ اصل مقصود ہے اورمن حمائٍ مَّسْنُون اس کے بیان کے طورپر استعمال ہواہے.اس ترکیب کے لحاظ سے اس آیت کے یہ معنے بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر بنانے والاہوں جو آواز دینے والی مٹی سے پیدا ہوگایعنے ایسے کیچڑ سے جو ایک خاص صورت میں ڈھالاگیاہو یعنی انسانی پیدائش ایسی پانی ملی ہوئی مٹی سے ہے جسے ایک خاص شکل دی گئی ہے.اوروہ کھوکھلی ہے جسے ٹھکورنے سے وہ آواز دیتی ہے.اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اول انسان مٹی سے پیداہواہے.دوم اسے خاص ترکیب دے کر ایسی طرح تیار کیاگیاہے کہ وہ اپنے اندر خلاء رکھتا ہے.سوم جب اسے ٹھکوراجاتاہے تو وہ آوازدیتاہے.اس کامطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے کی طاقت ہے جس طرح خلادار چیز کو ٹھکوریں تووہ بولتی ہے.اسی طرح انسان کو جب اللہ تعالیٰ ٹھکورتاہے یعنے اس کا امتحان لیتا ہے توجو انسان سلامت او راچھاہوتاہے وہ اللہ تعالیٰ کے ٹھکورنے پر جواب دیتاہے اوراس میں سے جواباً آواز آتی ہے اوریہی خصوصیت انسان کی ایسی ہے جو اسے دوسری اشیاء سے ممتاز کرتی ہے یعنی انسان کے اند ر اللہ تعالیٰ کے امتحان کو قبول کرنے کی اورپھر اس کا جواب دینے کی قابلیت ہے.یہ کہ وہ صورت جس میں انسان پہلے بنایاگیا اورجس پر حَمَائٍ مَّسْنُون کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کیا تھی اس کاقرآن کریم نے ذکر نہیں کیا.ممکن ہے وہ بالکل غیر مرئی ہو اورخورد بینی ہو.بہر حال جو صورت مٹی سے انسان کو ابتداً ملی.وہ اسی وقت سے صلصال تھی یعنے یہ قابلیت رکھتی تھی کہ خدا تعالیٰ اس کا امتحان لے اوروہ اس کا جواب دے.قرآن کریم انسانی پیدائش میں ارتقاء کا قائل ہے اس مضمون سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم انسانی پیدائش میں ایک ارتقا ء کاتوقائل ہے.مگر ایسے ارتقاء کانہیں جو اتفاقاً ہوگیابلکہ وہ انسانی پیدائش کو درجہ بدرجہ توبتاتا ہے لیکن یہ نہیں تسلیم کر تا کہ انسان بننے والا ذرہ کسی وقت بھی انسان کے سوا کچھ اورتھا بلکہ اس کے نزدیک وہ جب بھی اورجس صورت میں بنا تھا اس میں انسان بننے اورالہام کو قبول کرنے کی قابلیت موجود تھی.اپنے تما م دوروں میں ایک خاص مقصد کی طرف وہ قدم بڑھا رہاتھا اورڈارون کی تھیوری کے مطابق یہ نہ تھا کہ اس کے بعض حصے نامکمل صورت میں الگ شاخوں میں تقسیم ہوتے گئے ہوں اور کچھ اچھے حصے الگ ہوکر آگے بڑھتے گئے ہوں.
Page 278
مسنون کے معنے صورت والی شے کے میں نے مسنون کے معنے صورت والی شے کے کئے ہیں گوعام طور پر مفسر اس کے معنے سڑی ہوئی شے کے کرتے ہیں (بحر محیط زیر آیت ھذا).اس کی وجہ یہ ہے کہ جیساکہ علامہ ابوحیان نے لکھا ہے سڑنے کے معنے اَسَنّ سے پیدا ہوتے ہیں جو رباعی مزید کاصیغہ ہے اوراس سے اسم مفعول کا صیغہ مسنون نہیں بلکہ مُسَنٌّ بنتا ہے.سَنَّ کے معنے ایک طریق کوجارے کرنے یاصورت دینے یاتیز کرنے یا مٹی کو پکاکر اسے ایسا بنادینے کے ہوتے ہیں کہ وہ آواز دینے لگے.مسنون کے معنی سڑی ہوئی مٹی کے مجازی ہیں پس سڑی ہوئی مٹی کے معنے ایک مجازی معنی ہیں.حقیقی معنے ایک خاص شکل پر بنائی ہوئی شے یاآواز دینے کے قابل بنی ہو ئی شے کے ہیں.الہام الٰہی کو عجیب سمجھنے والوں کو جواب اس آیت میں ان لوگوںکا جواب دیا ہے جو الہام الٰہی کو عجیب سمجھتے ہیں اورحیرت کرتے ہیں کہ انسان کو الہام ہو کس طرح سکتاہے اورفرمایاکہ تعجب کے قابل یہ بات نہیں کہ الہام کیونکر ہوتا ہے تعجب اس بات پر ہونا چاہیے کہ کسی کو الہام کیوں نہ ہو.کیونکہ انسانی پیدائش کی ابتداء سے الہا م کی قابلیت انسان میں رکھی گئی ہے اوراس کی پیدائش کی غرض ہی یہ تھی کہ وہ کامل ہو کر الہام الٰہی کو حاصل کرے پس اس پر تعجب نہ کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیونکر ہوگیا.یا اس الہام کی حفاظت کے لئے آئندہ اس کے اَتْباع کو کس طرح الہام ہوگا.تعجب اپنی حالت پر کرو کہ من صلصال ہوتے ہوئے تم کو کیوں الہام نہیں ہوتا.اوراپنی حالت کے بدلنے کی طرف توجہ کرو.قرآن کریم میں جہاں خلق آدم کا ذکر ہے اس سے پہلے حشر کا ذکر یا بعث بعد الموت کا ذکر اس آیت سے پہلی آیت یہ ہے وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ١ؕ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ.اس کے بعد اس آیت میں خلق آدم کا ذکر شروع کیا ہے.یہ کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتاہے کہ جہاں بھی خلق آدم کا ذکر ہے اس سے پہلے حشر کا ذکر یابعث بعدالموت کے واقعات میں سے کسی حصہ کا ذکر ضرورموجو دہے.بقرۃ اور اعراف میں آدم کی پیدائش کا ذکر چنانچہ(۱)بقرہ میں آدم کی پیدائش کا ذکر کیا ہے.اس سے پہلے فرمایا ہے.کَیْفَ تَکْفُرُوْنَ بِاللّٰہِ وَکُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْیَاکُمْ ثُمَّ یُمِیْتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ ثُمَّ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ (البقرۃ:۲۹).تم اللہ تعالیٰ (کی طاقتوں )کاکس طرح انکار کرتے ہو.حالانکہ تم پہلے بے جان تھے.اس نے تم کو جان دی پھروہ تم کو مارے گا اورپھر زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جا ئوگے.یہاں بھی موت حیات اورپھر اس کی طرف جانے یعنے حشر کا ذکر ہے (۲)سورئہ اعراف میں آدم کا ذکر ہے وہاں بھی اس سے پہلے حشر کا ذکر کیا ہے
Page 279
یعنی رکوع اول میں توحشر کا ذکر ہے اور رکوع دوم میں آدم کی خلق کا.(۳)الحجر کی زیر تفسیر آیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے حشر کا ذکر ہے اوربعد میں ساتھ ہی خلق آدم کا(۴)سورہ کہف میں بھی خلق آدم کا ذکر ہے.وہاں بھی پہلے جزاوسزااورمر کر اُٹھنے کا ذکر ہے.پھر خلق آدم کا.فرمایا وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً١ۙ وَّ حَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا.وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا١ؕ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۭ١ٞ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا.(الکہف:۴۷ ، ۴۹)اورپھر فرمایا وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ۠ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ الآیۃ (الکہف:۵۱) (۵) طٰہٰ میں جہاںآدم کا ذکر ہے وہاں پر بھی رکوع ۵ میں حشر کا ذکر ہے فرماتا ہے يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَىِٕذٍ زُرْقًا(طٰہٰ:۱۰۳) اوراس کے آگے تفصیلات بھی حشر کی بیان ہو ئی ہیں.پھر رکوع چھ کے آخر میں اوررکوع سات میں آدم کی پیدائش کا ذکرشروع ہوگیا ہے.فرماتا ہے وَلَقَدْ عَھِدْنَااِلیٰ اٰدَمَ(طٰہٰ:۱۱۶) الآیہ(۶)سورئہ ص میں بھی دوزخ و جنت کا ذکر کرکے حضرت آد م ؑ کا ذکر کیاہے.(رکوع۴و۵)غرض ان ساری آیات پر غور کر نے سے ایک معاند قرآن بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے والے کے ذہن میں کوئی ترتیب ضرور ہے اوروہ لو گ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ترتیب نہیں وہ غلطی پر ہیں ورنہ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ اوردیگر انبیاء کا ذکر تو بغیر حشر کے ذکر کے آجائے مگر جہا ں بھی حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر آئے اس سے پہلے حشر کا ذکر ضرورہو.خواہ وہ منکر اس ترتیب کو سمجھے یانہ سمجھے.بہر حال اس پر اس قدر تو ضرور ثابت ہو جائے گاکہ قرآن کریم کے نازل کرنے والے کے ذہن میں ضرور کوئی خاص ترتیب تھی جس کی وجہ سے آدم ؑکا ذکر ہمیشہ حشر کے ذکر کے ساتھ آتاہے.قرآن کریم میں اسلام کی آئندہ ترقی کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں ایسی کئی مثالیں ہیں کہ کئی جگہ پر ایک ہی طرز کا ذکر بار بار ہوتاہے.مثال کے طور پر میں ایک بات کو بیان کرتاہوں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں اسلام کی آیندہ ترقی اورعالمگیر تبلیغ کا ذکر آتاہے وہاں پر ضرورحضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے.تمام قرآن کریم میں تین جگہ یہ ذکر ہے اورتینوں جگہ مسیح علیہ السلا م کا ذکر ہے.سورۃ بقرۃ کی کنجی میرے نزدیک قرآن کریم کے مضامین کی ایک نہ ایک کنجی ضرور ہوتی ہے.بعض وقت اس کنجی کا علم الہام کے ذریعہ سے ہو جاتا ہے.اوربعض وقت انسان خود غوروفکر کرکے اپنی عقل سے مددلے کر اس کو پالیتا ہے.مجھے ایک دفعہ بطور القاء بتایاگیاتھا کہ سورہ بقرہ کی کنجی يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ والی آیت ہے.چنانچہ میں نے اس کنجی کی مدد سے تمام بقرہ کو حل کرلیاتھا.
Page 280
ہر سورۃ کی کنجی ایسا ہی ایک دفعہ خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا کہ بِسْمِ اللہ ہرایک سورۃ کی کنجی ہے.تبھی ہر سورۃ کے ساتھ نازل ہوئی ہے(سورہ توبہ علیحدہ کوئی سورۃ نہیں بلکہ انفال کا حصہ ہے )یہ تو ایک ضمنی بات بیان ہوگئی.حشر اور آدم کے واقعات میں گہرا تعلق میں یہ کہہ رہاتھا کہ ہر جگہ حشر کے ساتھ آدم کامذکورہونا بتلاتاہے کہ ان دونوں امور میں گہراتعلق ہے.وہ تعلق کیا ہے؟ حشر اور آدم کے واقعات کا پہلا تعلق اول تویہ تعلق ہے کہ حشر اجساد کامسئلہ کلی طور پر آدم کی پیدائش کے ساتھ وابستہ ہے.کیونکہ اگر ایک عاقل و قادروجود نہ ہو توحشر اجساد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.حیوانات کسی شریعت پر عامل نہیں کیونکہ وہ معذور ہیں.اس لئے کسی سزاجزاکے مستحق نہیں اور کسی حقیقی حشر کے محتاج نہیں.فرشتے بھی کسی جزاوسزا کے مستحق نہیں کیونکہ گووہ نیک ہیں لیکن بہرحال مجبورہیں اوریَفْعَلُوْنَ مَایُؤمَرُوْنَ (نحل :۵۱)کے مقام والا کسی حشر کا محتاج یا مزید جزاء کا مستحق نہیں ہوتا.شیطان کی پیدائش انسان کے تابع ہے.مگر بہرحال انسان کے سواجو بھی شیطان ہے وہ کسی سزا کا مستحق نہیں کیونکہ اپنا فرض پوراکررہاہے.جس طرح ا س دنیا کی گندی اشیاء سزا کی مستحق نہیں کہ وہ کیوں گندی ہیں.اسی طرح انسان کے سوا جو شیطان ہیں.و ہ بھی سزاکے مستحق نہیں ہاں جو انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ ضرور سزا کے مستحق ہیں اورحشر انہی بد انسانوں اورنیزنیک انسانوں کے لئے مقرر کیاگیا ہے.خلق انسان حشر کی دلیل ہے پس پیدائش انسانی ہی حشر کاموجب ہے.اور اس وجہ سے ہرجگہ جہاں آدم کی پیدائش کا ذکر ہے اس سے پہلے حشر کا ذکر کیاگیاہے تابتایاجائے کہ انسانی پیدائش کا تقاضاہے کہ کوئی حشر ہو اورحشر کا تقاضا ہے کہ کوئی شریعت ہو ورنہ بغیر حجت کے سزاجزابے معنی ہوجاتی ہے.دوسرا تعلق دوسراتعلق ان دونوں مضامین کا یہ ہے کہ خلق انسانی حشر کی دلیل ہے.میں بعض دلائل اس دعویٰ کی تائید میں ذیل میں درج کرتا ہوں :.(۱) انسانی پیدائش کائنات کی ادنیٰ ترین حالتوں سے ترقی کرکے مکمل ہوتی ہے.پس یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی دارالجزاء بھی ہے.اگر انسان پہلے سےہی ایک خلقت میں پیدا ہوتا.توکہا جاسکتاتھا کہ یہ اتفاقی واقعہ ہے دوسری چیزیں بھی طبعی تغیرات کے نتیجہ میں بن گئی تھیں.یہ بھی بن گیا.لیکن ادنیٰ حالتوں سے مختلف تغیر ات کے بعد انسان کابننا اورانسان کے بن جانے کے بعد نئی مخلوق کے لحاظ سے ترقی کارک جانا یہ بتاتا ہے کہ انسانی پیدائش ایک ارادے کے ماتحت تھی اورتخلیق کا مقصود تھی.(۲) دنیا میں دوطاقتو ں کاوجود پایا جاتاہے ایک طاقت خیر کی ہے اوردوسری شرّ کی ہے.انسان کے اند ران
Page 281
دونوں طاقتوں کاپایاجانا اورپھر اس میں دونوں پر قبضہ پانے کی قابلیت کاہونا بتاتا ہے کہ انسان کو دنیا پر حکومت کرنے کے لئے بنایا گیا تھاپس اس کی زندگی کانتیجہ اس کے عمل سے کچھ زیادہ ہوناچاہیے اوراس کا تقاضا حشرہے.(۳)اس دنیا کی ترقیات طبعی قوانین سے وابستہ ہیں نہ کہ اخلاقی اور روحانی امور سے اورانسانی پیدائش صاف طور پر ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے وجود کا بڑ اجزو اخلاقی اور روحانی حالات ہیں.پس اس دنیا کی ترقیات اس کے لئے منزل مقصود نہیں ہوسکتیں اوراخلاقی اور روحانی قربانیوں کے لئے کوئی اورمقام جزاہوناچاہیے.یہ جو فرمایا ہے مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ اس سے یہ بتایاگیا ہے کہ انسان کی پیدائش پانی اورمٹی سے ہے کیونکہ حَمَائٍ مٹی اورپانی کی ملی ہوئی چیز کو کہتے ہیں.دوسری جگہوں پر خدا تعالیٰ نے علیحد ہ علیحدہ ان دونوں چیزوں سے پیدائش کا ذکر کیا ہے.مثلاًپانی کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآئِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ (الانبیاء :۳۱)د وسری جگہ مٹی سے پیدائش کویوں ظاہر فرمایا ہے کہ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ١ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ(آل عمران :۶۰) ان دونوں آیتوں میں توپیدائش کا ذکر علیحدہ علیحدہ طور پر پانی اورمٹی سے کئے جانے کاکیا ہے.مگریہاں سورۃ الحجر میں دونوں کو جمع کردیا ہے کہ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ سے انسان پیداہواہے.یعنی اس مٹی سے جس میں پانی ملایاگیا اورپھر ایک خاص صورت دے کر اسے بولنے کے قابل بنایاگیا چنانچہ مِنْ صَلْصَالٍ کہہ کر قوت ناطقہ کی طرف واضح طور پر اشارہ کردیاگیا ہے.اوربتایاہے کہ ایک حد تک سب ہی حیوانوں کی پیدائش حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ سے ہوئی ہے.لیکن انسانی پیدائش میں حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ کی صفت صلصالیت کاظہور نمایاں ہے.اسی لحاظ سے انسان کو حدیث میں صالّۃ بھی کہاگیا ہے.اور وہ بھی صلصال کی طرح کالفظ ہے.پس کوئی وجہ نہیں کہ صال کالفظ تو انسان کے لئے بولاجاوے مگر صلصال کالفظ نہ بولا جائے اس لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کابولنا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے.کیونکہ صلّ یا صلصل ایسی آواز پر دلالت کرتاہے جو ٹھکورنے سے پیداہوتی ہے اوریہی حقیقت انسان کی ہے کہ وہ کلام جس کی خاطراس کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس میں سے تبھی پیدا ہوتاہے جب اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ٹھکوراجاتاہے یعنی الہام الٰہی نازل ہوتاہے اوراس کو مشکلات اورمشقتوں سے گذاراجاتاہے.انسان کےمِنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ سے بنائے جانے کا مطلب اوریہ جو فرمایاکہ انسان حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ سے بنایاگیا.اس کایہ مطلب نہیں کہ وہ بے جان مٹی سے بن گیاہے بلکہ(۱) چونکہ حیوانی مادہ بغیر جسم کے ترقی نہیں کرسکتا اور جسم مٹی سے بنتا ہے اس لئے اس کی طر ف اشارہ کیاہے کہ تاانسان کومعلوم ہو کہ اس کی ابتداء کہاں سے
Page 282
ہوئی ہے.آیت مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ سے انسان کی ابتداء کی طرف اشارہ نہیں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سائنس کا یہ دعویٰ کہ حیوانی مادہ حیوان سے ہی پیداہو سکتا ہے.خود قابل تحقیق ہے کیونکہ اس کی دلیل صرف ہماراموجودہ مشاہدہ ہے اوریہ امر ظاہر ہے کہ جس وقت یہ حیوانی مادہ پیداہوااس وقت کے حالات اورموجودہ حالات میں بڑافرق ہے.سائینس بھی اس امر کو تسلیم کرتی ہے کہ یہی حیوانی مادہ کسی وقت میں ترقی کرکے انسان بن گیاتھالیکن اب ویسا نہیں ہوتا پس اس سے صاف معلوم ہوتاہے کہ ابتدائے آفرینش کے حالات میں اوراس وقت کے حالات میں بہت بڑا تغیر ہے.اس وقت زندگی پیداکرنے کی رَو نہایت ہی تیزتھی اوراب اتنی نہیں.پس ہو سکتا ہے کہ ان حالات کے ماتحت بے جان ذرات ہی بعض تغیرات کے ماتحت زندہ ذرات میں تبدیل ہوجاتے ہوں اوربعد میں زمین کے کامل ہوجانے پر وہ حالات نہ رہے ہوں.پس متفرق حالات کا ایک دوسرے پر قیا س کرنا سائینس نہیں کہلاسکتا.مٹی سے یکدم انسان نہیں بنا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ مٹی سے یکدم انسان بن گیا کیونکہ قرآن کریم خلق عالم کی تدریجی پیدائش پر بار بار زور دیتا ہے اورہم دیکھتے ہیں کہ تناسل والی خلق میںبھی (قرآن میں اَللّٰہُ یَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ (یونس:۳۵) فرماکر دوحلقوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے )تدریج پائی جاتی ہے (یہ نہیں ہوتا کہ ادھر میاںبیوی ملیں تو ادھر بچہ پیداہوجائے)توکیوں پہلی خلقت میں تدریج نہ ہوگی؟ پس اس آیت میں صرف اس ابتداء کی طرف اشارہ ہے جس وقت حیوانی قابلیتوں سے ترقی کرکے انسان میں اس کی امتیازی قابلیت پیداہوئی اوروہ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ کی صلصال والی حالت ہی تھی یعنی جس میں قبولیت الہا م کا مادہ پیداہوایایہ سمجھیں کہ صرف اس کی اس ابتداء کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں سے اس کی حیات محض شروع ہوئی تھی.اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیونکر تسلیم کیاجائے کہ اس سے انسانی یاحیوانی پیدائش کی ابتداء کی طرف اشارہ ہے اورکیوںنہ سمجھاجائے کہ قرآن کریم کے نزدیک انسان کی پیدائش کی ابتداء ہوئی ہی اسی طرح تھی کہ مٹی کا پُتلابنایا اور اس میں جان ڈال دی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودقرآن کریم سے ثابت ہے کہ اس آیت میں ابتداء کا ذکر نہیں چنانچہ سورئہ روم ع۳ میں آتاہے اَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ (الروم :۲۱)کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو خشک مٹی سے پیدا کیاہے پھر تم بشر بن گئے اوردنیا بھر میں پھیل گئے.اب یہ امر آیت زیر تفسیر کے خلاف ہے کیونکہ اس میں حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ سے پیدائش انسانی لکھی ہے اوراس آیت میں تراب یعنی خشک مٹی سے لکھی ہے.
Page 283
انسانی پیدائش کی مختلف کڑیوں کا ذکر پس معلوم ہواکہ خشک مٹی ابتدائی کڑی ہے مگر سورہ حجر میں اس ابتدائی ذکر کو چھو ڑ کر اس کے بعد کی حالت کو بیان کردیاگیا ہے.سورۃ فاطرع۲ میں اوربھی فرق کردیاگیا ہے وہاں فرماتا ہے.وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ (فاطر:۱۲)یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو خشک مٹی سے پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد نطفہ سے.اس آیت میں اول توحمائٍ مسنون کو ترک کردیاہے.دوسرے تراب کے بعد پیدائش کی ایک اورکڑی بیان کی ہے جو نطفہ ہے.سورہ مومن میں اس سے بھی مختلف پیرایہ میں پیدائش کا طریق بتایا ہے.فرماتا ہے هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا (المؤمن:۶۸) کہ نطفہ کے بعد بھی یکدم انسان نہیں بنا.بلکہ اس کے بعد ایک اورتغیّر ہواہے اوروہ یہ کہ نطفہ علقہ بنا اورپھر اس سے انسان بنا.انسانی پیدائش مختلف حالات سے گزر کر ہوئی مگر سورئہ حج میں اس میں بھی زیادتی کردی گئی ہے اورفرمایا ہے فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَیْرَ مُخَلَّقَۃٍ (الحج:۶) کہ علقہ کے بعد بھی یکدم انسان نہیں بنا بلکہ اس کے بعد ایک اوردرجہ ہے یعنی علقہ سے مضغہ بنتاہے اوروہ مضغہ بھی دوطرح کاہوتاہے کامل اورغیر کامل پھراس سے انسان بنا.مگراس پر بھی بس نہیں.سورئہ مومنون میں ان کڑیوں پر اورزیادتی کی گئی ہے فرماتا ہے وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ.ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ.ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا١ۗ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ١ؕ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ.(المؤمنون:۱۳ تا ۱۵) یہاں پر تین کڑیاں زائدبیان کی ہیں اوربتایاہے کہ مضغہ کے بعد بھی یکدم انسان نہیں بنا بلکہ پہلے عظام بنتی ہیں پھر عظام پر گوشت چڑھایاجاتاہے پھر ایک اورپیدائش ہوتی ہے کہ ان بظاہر بے جان مادوں سے ایک جاندار شے پیداہوجاتی ہے.ان آیات پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتاہے کہ قرآن کریم بعض دفعہ درمیانی وسائط کوچھوڑ دیتا ہے پس حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک مٹی کا ایک بت بنا کر اس میں روح ڈال دی گئی تھی اوروہ چلتا پھرتاانسان بن گیاتھا بلکہ قرآن کریم کی تعلیم سے ظاہر ہے کہ انسانی پیدائش مختلف حالات سے گذر کر ہوئی اورمٹی کے الفاظ دیکھ کر یہ نتیجہ نہیں نکال لینا چاہیے کہ انسان فورًامٹی سے گھڑ کر بنادیاگیاتھا(جیسے کہ عوام کا خیال ہے)بلکہ صرف اتنا مطلب ہے کہ مٹی سے ابتداہوئی اوریہ امر یقینی طورپر ثابت ہے کیونکہ انسان اب بھی اپنی غذامٹی سے ہی حاصل کرتاہے اور کسی چیز کی غذااسی سے لی جاتی ہے جس سے وہ چیز بنی ہو.ورنہ غذاغذاہی نہیں بن سکتی.مثلاً لوہا اگر گھس جائے تو اس کی جگہ لوہا ہی لگایاجائے گا دوسری چیز اس کاکام نہیں دے سکتی.پس ہماری غذاچونکہ مٹی کے اجزاء سے بنتی ہے یہ
Page 284
ظاہر ہے کہ ہماری پیدائش بھی اسی قسم کے اجزاء سے ہے جو مٹی کے تیار کرنے میں خرچ ہوئے ہیں اورانسان پیدائش عالم کی آخری ارتقائی کڑی ہے کوئی باہر سے آئی ہوئی شے نہیں.میں اس جگہ انسانی پیدائش پر تفصیلی بحث نہیں کرتا اس کا مناسب مقام سورئہ بقرہ یاسورئہ اعراف کی آیا ت ہیں.وَ الْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ۰۰۲۸ اور(اس سے) پہلے جنّوں کو یقیناً ہم نے سخت گرم ہواکی (قسم کی )آگ سے پیدا کیاتھا.حلّ لُغَات.اَلْجَانَّ:الجَانَّ جَنَّ یُجُنُّ جَنًّاوَ جُنُوْنًا کے معنے ہیں.سَتَرَ ہٗ وَاَظْلَمَ عَلَیْہِ پردہ ڈال دیااوراندھیرکردیا.جَنَّ الَّیْلُ:اَظْلَمْ وَاخْتَلَطَتْ ظُلْمَتُہٗ.رات کی تاریکی چھا گئی.وَجَنَّ الْجَنِیْنُ فِی الرَّحْمِ اِسْتَتَرَ.جنین رحم میں پوشیدہ ہوگیا.وَالْـجَانُّ اِسْمُ فَاعِلٍ اور جانّ اسم فاعل ہے یعنی اندھیرا کردینے والا.یاپوشیدہ ہوجانے والا.وَاِسْمُ جَمْعٍ لِلجِنِّ.اوریہ جنّ کی اسم جمع بھی ہے.حَیَّۃٌ بَیْضَاءُ کَحْلَاءُ الْعَیْنِ لَاتُؤْذِیْ.اوراس سفیدسانپ کو بھی جو سرمگین آنکھوں والاہو جانّ کہتے ہیں.ایسے سانپ میں زہر نہیں ہوتااوروہ کاٹتا نہیں (اقرب) وَالْجَانَّ اَبُوْالْجِنِّ اورجنّوں کے مورث اعلیٰ کوبھی جانّ کہتے ہیں.(تاج) السّموم:السَّمُوْمُ سَمَّ یَسُمُّ سَمًّا سے اسم ہے.سَمَّ الطَّعَامَ کے معنے ہیں.جَعَلَ فِیْہِ السَّمَّ کھانے میں زہر ڈال دیا.سَمّ الْاَمْرَ کے معنے ہیں.سَبَرَہُ ونَظَرَ غَوْرَہُ کہ معاملہ کی تحقیقات کی اوراس کی حقیقت معلوم کی.سَمَّتِ الرِّیْحُ سُمُوْمًا.اَحْرَقَتْ گرم ہوانے چیزوں کو جھلس دیا.والسَّمُوْمُ:الرِّیحُ الحارَّۃُ ،سموم گرم ہواکوبھی کہتے ہیں.اس کی جمع سَمَائِمُ ہے.وَقَالَ اَبُوْعَبِیْدَۃَ السَّمُوْمُ بِالنَّہَارِ وَقَدْ تَکُوْنُ بِاللَّیْلِ.اورابوعبیدہ نے کہاہے کہ سموم دن کو ہوتی ہے اور کبھی کبھی رات کو بھی.اَلْحَرُّالشَّدِیْدُ النَّافِذُ فِیْ الْمَسَامِّ اورسموم اس شدت گرمی کو بھی کہتے ہیں جو مسامات میں گھس جانے والی ہو.(اقرب) محیط میں لکھا ہے کہ ابن عباسؓ نے کہاہے سموم اس شعلہ والی آگ کو کہتے ہیں.جس میں دھواں نہ ہو یعنی شعلہ والی آگ یاانگارہ والی(بحر محیط زیر آیت ولقد خلقنا الانسان من صلصال).ان سارے معنوں کو مدنظر رکھیں تومعلوم ہوتاہے کہ اَلسَّمُوْمُ اس چیز کو کہتے ہیں جو باریک طور پر اند ر گھس جائے اورپھر اثر کرے.سمّ(زہر)کو بھی سَمّ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی عروق کے ذریعہ جلد انسان کے جسم میں سرایت کرجاتا ہے اورفورًاانسانی زندگی کا خاتمہ کردیتاہے چنانچہ بعض ایسے زہر بھی ہیں جو صرف سونگھنے
Page 285
سے یاصرف جسم پر ملنے سے اثر کرجاتے ہیں.تفسیر.جانّ جیساکہ لغت سے ظاہر ہے جنّ کا اسم جنس بھی ہے اوراس کے معنے پردہ ڈالنے والے یااندھیر اکردینے والے کے بھی ہیں.اورتاریک ہو جانے اورپوشید ہ ہونے کے بھی.پس وضع لغت کے لحاظ سے ہر وہ شے جو دوسری شے کو پوشیدہ کردے.اس پر پردہ ڈال دے یاتاریک کردے وہ جنّ ہے.یاہر وہ شے جو خود تاریکی میں بڑھ جائے یا نظرو ں سے پوشیدہ ہویاپوشیدہ ہوجائے جنّ ہے.جنوں کے متعلق عام لوگوں کا خیال عام خیال کے مطابق جنّ ایک ایسی مخلوق ہے جوانسانو ںکو نظرنہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرے.اس قسم کی مخلوق کے متعلق دنیا میں عام خیا ل پایا جاتا ہے بعض قومیں یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ فرشتے ہی اچھے اور بُرے ہوجاتے ہیں اور اس طرح وہ فرشتوں اورشیطانوں یا جنّوں کو فرشتو ں کی دو قسمیں قرار دیتے ہیں.جنوں کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہندوئوں میں یہ خیال پایاجاتا ہے کہ گندھروا اوراپسرا دو قسم کی ارواح ہیں جو نظرنہیں آتیں.گندھرواخشکی کی روحیں ہیں اوراپسراسمندری روحیں ہیں.دونوں کے ملنے سے نسل انسانی چلی ہے.چنانچہ ان کے نزدیک گندھروا اوراپسرا سے یامااوراس کی توام بہن یامی پیداہوئی اوریہ پہلا انسانی جوڑا تھا.گندھروا کے متعلق ان کا خیال ہے کہ ان کی الگ زمین ہے اورالگ گھوڑے ہیں اودریائے سندھ کے اس پار رہتے ہیں.چنانچہ ان کے نزدیک ٹکسلا کاشہر بھی گندھروادیسا میں ہے (انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ گندھروااورجلد دوم زیر لفظ اپسراAPSARAS) جنوں کے متعلق زردشتیوں کا عقیدہ زردشتیو ںمیں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے مگر کسی قدر اختلاف کے ساتھ.ان کے نزدیک خدادوہیں ایک نیکی کا خدااوراس کانام اہرمزدہے اورایک بدی کا خدااس کانام اہرمن ہے.نیکی کے خدا کا بھی ایک لشکر ہے.جن کو فرشتے کہناچاہیے.اسی اہرمن کابھی ایک لشکر ہے جسے ہماری اصطلاح میں شیطانوں کی جماعت کہناچاہیے.یونانیوں میں بھی بعض اچھی اوربری ارواح کاخیال پایاجاتاتھا.چنانچہ فیثا غورس اورافلاطون کے تابعین میں یہ خیال پایاجاتاتھاکہ انسانوں کے علاوہ بعض نہ نظر آنے والی ارواح ہیں جن میں سے کچھ بداور کچھ نیک ہیں.(انسائیکلو پیڈیا ببلیکا زیرلفظ ڈیمن DEMONS) یہود میں فرشتوں اورشیطانوں کی صورت میں نہ نظر آنے والی ہستیوں کے وجود کااقرارپایاجاتا ہے چنانچہ
Page 286
صحف موسیٰ میں فرشتوں کا ذکربھی موجود ہے اورشیطانوں کا بھی اورگندی ارواح کابھی.چنانچہ فرشتو ں کا ذکر حضرت یعقوب کی خواب میں ہے ’’اورخواب دیکھا اور کیا دیکھتاہے کہ ایک سیڑھی زمین پر دھری ہے اوراس کا سراآسمان کو پہنچا ہےاوردیکھوخداکے فرشتے اس پر سے چڑھتے اُترتے ہیں.‘‘ (پیدائش باب۲۸آیت ۱۲) شیطان کا ذکر حضرت آدم کے قصہ میں آتاہے جب شیطان نے حضرت حوّاکو ورغلا کر ممنوع درخت کا پھل کھلایا (پیدائش باب ۳ آیت ۱ تا ۵).اس جگہ اس کانام سانپ رکھا ہے لیکن مراد شیطان ہی ہے اورسانپ سے جن یا بدروحوں کو مراد لینا قدیم محاورہ ہے.عربی زبان میں بھی سانپ کاایک نام جانّ ہے اورہندوئوں یونانیوں وغیرہ میں بھی یہ خیا ل پایا جاتا ہے کہ بعض سانپ جنات کی قسم سے ہیں.بد ارواح کا ذکر بائیبل میں بدارواح کا ذکر استثناء باب ۳۲آیت ۱۷میں یوں آتاہے’’انہوں نے شیطان کے لئے قربانیاں گزرانیں نہ خداکے لئے بلکہ ایسے معبودوں کے لئے جن کو آگے وے نہ پہچانتے تھے جو نئے تھے اورحال میں معلوم ہوئے اوران سے تیرے باپ دادے نہ ڈرتے تھے.‘‘اس جگہ شیطانوں سے مراد بدارواح ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل انہیں پہلے نہ جانتے تھے.ورنہ شیطانوں کو تووہ جانتے تھے.یہود کے لٹریچر میں جنات کا ذکر بائبل کے علاوہ یہود کے لٹریچر میں جنّات پر خاص زورہے شرکی ربیّ الیعذر میں لکھا ہے کہ جنّ شمالی علاقوں میں رہتے ہیں اورمیگاتی میں لکھاہے وہ فرشتوں کی طرح اُڑتے ہیں.شبات طالمود میں لکھاہے.انسان ان سے تعلق رکھ سکتے ہیں اوروہ آسمان کی خبریں سن لیتے ہیں (جیوئِشْ انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ ڈیمن DEMON) اناجیل میں جنوں کا ذکر مسیحیوں میں بدارواح کا ذکر خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اناجیل میں بدروحوں کے نکالنے کو یسوع کاخاص کام بتایا ہے بلکہ ان کے بعد ان کے حواری بھی بدروحوں کو نکالتے رہے.اناجیل کے بیان کے مطابق تویو ں معلوم ہوتاہے کہ اس زمانے میں جنّات دیوانے ہورہے تھے ہرشہراور ہر قصبہ میں لوگوںپر آکر قبضہ کرلیتے تھے اوربعض دفعہ تو سینکڑوں آدمیوں پر یکدم قبضہ کرلیتے تھے (دیکھو متی باب۸،۶و۲۸مرقس باب۱،۳۲و ۳۴) مسلمانوں کے نزدیک نظر نہ آنے والی ارواح کی تین اقسام مسلمانوں کا عام عقیدہ یہ ہے کہ نظر نہ آنے والی ارواح تین قسم کی ہیں (۱) فرشتے جو سب نیک ہیں بعض کے خیال میں ان میں سے بعض بد بھی ہوجاتے ہیں جیسے کہ شیطان کہ وہ پہلے فرشتہ تھایاہاروت ماروت(۲)شیطان کہ وہ سب برے ہوتے ہیں (۳)جنّ کہ وہ نیک بھی ہوتے ہیں او ر بد بھی جو جنّ بدہوتے ہیں وہ لوگوں پر قبضہ کرلیتے ہیں اوربعض تدابیر سے جنّوں پر قبضہ بھی کیا
Page 287
جاسکتاہے اوران سے کام بھی لیاجاسکتا ہے (قرطبی سورۃ الحجر زیر آیت فسجد الملائکۃ).قرآن مجید میں جنوں کا ذکر قرآن کریم میں جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے فرشتوں،شیطانوں اورجنّوں تینوں کا ذکر ہے اوریہ بھی معلوم ہوتاہے کہ جن نیک بھی ہوتے ہیںاوربد بھی جیساکہ سورئہ جنّ میں آتا ہے مِنَّا الصّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِکَ(الجن :۱۲)یعنی جنوں نے ایک دوسرےسے کہاکہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اوربرے بھی اوریہ بھی معلوم ہوتاہے کہ جن انسانوں کی تابع بھی ہوجاتے ہیں اوران کے کام کرتے ہیں جیسے حضرت سلیمانؑ کے بارہ میں آتاہے وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ(سبا :۱۳) یعنے جنوں میں سے بھی کچھ افراد حضرت سلیمانؑ کے حکم کے ماتحت اوراللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کے کام کیاکرتے تھے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ جنّ حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لائے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے.احادیث میں جنوں کا ذکر احادیث میں بھی جنوں کا ذکر ہے لکھا ہے کہ جنوں کا ایک قافلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لئے آیا (مسلم کتاب الصلٰوۃ باب الجہر بالقرأۃ...)اوریہ بھی آتا ہے کہ ہڈی گوبر وغیرہ جنّوں کی غذا ہیں اس لئے ان سے استنجا نہیں کرناچاہیے.(ترمذی ابواب الطہارۃ باب کراھیۃ ما یستنجی بہ و ابوداؤد کتا ب الطہارۃ باب ما ینھی عنہ ان یستنجی بہ) علامہ سندھی مصنف مجمع البحار لکھتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ ؒ کایہ مذہب تھا کہ نیک جنّات صرف عذاب سے نجا ت پائیں گے جنت میں نہیں جائیں گے.لیکن امام مالکؒ اورامام بخاریؒ کایہ مذہب تھا کہ وہ جنت میں بھی جائیں گے اورانہیں ثواب ملے گا.مجمع البحا ر میں ہی ابن عربی کاقول نقل کیا ہے کہ سب مسلمانوں کایہ مسلّمہ مسئلہ ہے کہ جنّ کھاتے پیتے اورنکاح کرتے ہیں.(مجمع البحار زیر لفظ جن) جن کے لفظ کاقرآن کریم اور احادیث میں کئی معنوں میں استعمال میرے نزدیک جنّ کا لفظ قرآن کریم اوراحادیث میں کئی معنوں میں استعمال ہواہے.اوریہ مختلف استعمال جنّ کے مختلف معنوں پر مبنی ہیں یعنی ’’ مخفی ہونے والا‘‘یا ’’مخفی کرنے والا‘‘ان معنوں کے رو سے مختلف اشیاء یا ارواح یاانسان جو عام طورپر نظروں سے اوجھل رہتے ہیں.یا وہ اشیاء یا ارواح یاانسان جو دوسری اشیاء پر پردہ ڈالتے ہیں جنّ کہلاتے ہیں.اور چونکہ یہ فعل مختلف وجودوں سے ظاہرہوتاہے.اس لئے مختلف چیزوں یا ہستیوںکا نام اسلامی اصطلاح میں جنّ رکھا گیا ہے.قرآن کریم میں مختلف مقاموں میں جنات کا ذکر قرآن کریم میںجنات کا ذکر مندرجہ ذیل مقامات میں آتا ہے (۱)سورۃ حجر کی زیر تفسیر آیت کہ اس میں جنات کی پیدائش کا ذکر ہے کہ وہ نارِ سمومْ سے پیداہوئے
Page 288
(۲)سورئہ رحمن آیت ۱۶میں فرماتا ہے وَ خَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ جنوں کو ہم نے ایک لپٹیں مارنے والے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے (۳)ابلیس کی نسبت بھی آتاہے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍوَّ خَلَقْتَہٗ مِنْ طِیْنٍ(الاعراف :۱۳و ص:۷۷)تونے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اورآدم کو پانی ملی ہوئی مٹی سے (۴)پھر ابلیس کی نسبت یہ بھی آتاہے کہ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ (الکہف :۵۱) وہ جنوں میں سے تھا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا.معلوم ہواکہ ابلیس کی ناری طینت اس کے جنوں میں سے ہونے کے سبب سے تھی.(۵)جنّ شہوانی قوتیں بھی رکھتے ہیں چنانچہ سورئہ رحمن میں جنت کی عورتوں کی نسبت فرماتا ہے کہ لَمْ یَطْمِثْہُنَّ اِنْسٌ قَبْلَھُمْ وَلَاجَانٌّ (الرحمن:۵۷) ان کو نہ انسانوں ،نہ جنوں نے اس سے پہلے کبھی چھواہوگا(یہ ذکرا س رکوع میں دودفعہ آیا ہے )(۶)سورئہ رحمن میں ایک یوم حساب کا ذکر ہے اس کے ذکر میں فرماتا ہے فَيَوْمَىِٕذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّ لَا جَآنٌّ(الرحمن :۴۰) اس دن انسانوں یا جنوں سے ان کے گناہوں کے بارہ میں پوچھانہ جائے گا بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایک عام تباہی ان پر لائی جائے گی.(۷)جنّ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے پیداکئے گئے ہیں.فرماتا ہے وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّالِیَعْبُدُوْنِ (الذاریات :۵۷)(۸)مشرک لوگ اللہ تعالیٰ اور جنات کے درمیان رشتہ داری بتاتے ہیں.وَ جَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا(الصافات :۱۵۹)(۹)مشرک لوگ جنوں کو خدا تعالیٰ کا شریک بتاتے ہیں وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَ بَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ.(الانعام :ا۱۰) انہوں نے جنوں میں سے اللہ تعالیٰ کے شریک تجویز کئے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اوربغیرکسی علم کے انہوں نے اللہ کے لئے لڑکے اورلڑکیا ں اپنے خیالوں میں بنارکھی ہیں.اسی طرح آتاہے.بَلْ کَانُوْا یَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ (سبا:۴۲)قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گاکہ کیامشرک انسان تم کو پوجتے تھے تووہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ یہ جنوں کو پوجتے تھے (۱۰)جنوں میں سے ایک گروہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتاہے اَلَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ(الناس:۶،۷)نیز وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْارَبَّنَآ اَرِنَاالَّذَیْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْھُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَالِیَکُوْنَامِنَ الْاَسْفَلِیْنَ (حٰم السجدہ :۳۰)اورکفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب !ہمیں ذراوہ جن اورانسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دکھا توسہی.کہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روندیں تاکہ وہ ذلیل ترین وجود ہو جائیں.نیز فرمایا.وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا(الانعام :۱۱۳) اوراسی طرح ہم نے ہرنبی کے دشمن بنائے ہیں جنّ شیطان بھی.اورانسان شیطان بھی.وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لئے جھوٹی باتیں سناتے رہتے ہیں.نیز فرمایا يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ
Page 289
اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ (الانعام :۱۲۹) اے جنوں کی جماعت تم نے بہت سے انسانوں کو خراب کیاہے (۱۱)جنّ دوزخ میں بھی جائیں گے فرماتا ہے.قَالَ ادْخُلُوْا فِٓیْ اُمَمٍ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِکُمْ مِنَّ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ فِی النَّارِ(الاعراف :۳۹) یعنی جب فرشتے کفار کی جان نکالتے ہیں.توان سے کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو جنّ اورانسان فوت ہوچکے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہوجائو نیز فرمایا.اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْۤ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ١ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ (الاحقاف :۱۹)یعنی یہ کفاربھی ان گروہوں میں جاشامل ہوں گے جوجنّوں اورانسانوںمیں سے پہلے گذر چکے ہیں.اورجن پر اللہ تعالیٰ کی حجّت پوری ہوچکی ہے اوروہ عذاب کے مستحق قرار پاچکے ہیں یہ سب لوگ گھاٹاپانے والے ہوگئے یہی الفاظ حَقَّ سے لے کر خَاسِرِیْنَ تک سورئہ حٰم سجدہ آیت ۲۶میں بھی مذکور ہیں.نیز فرماتا ہے.وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ١ۖٞ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا١ٞ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا١ٞ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا(الاعراف :۱۸۰)اورہم نے بہت سے جنّوں اور انسانوں کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے اوریہ وہ ہیں کہ جن کو دل دئیے گئے مگرانہوںنے ان سے سمجھنے میں کام نہ لیا.انہیں آنکھیں دی گئیں مگرانہوں نے ان سے دیکھانہیں.انہیں کان تو دیئے گئے لیکن انہوں نے ان سے سنا نہیں.(۱۲) بعض انسان بعض جنّات کی پناہ میں رہتے ہیں اوراس وجہ سے جنّ مغرورہوجاتے ہیں وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا(الجن:۷)یعنےحقیقت یہ ہے کہ کچھ مردانسانوں میں سے جنّوں کے مردوں کی پناہ لیتے تھے اس طرح انہوں نے جنّوں کواور بھی ظلم اورگناہ میں بڑھادیا.(۱۳)جنّ انسانوں کاکام بھی کرتے ہیں.چنانچہ حضرت سلیمان کے ماتحت وہ کام کرتے تھے.فرماتا ہے.وَ حُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ (النمل:۱۸)سلیمان کے حکم کو پوراکرنے کے لئے جنّوں اورانسانوں کے لشکر جمع کئے گئے.نیز فرماتا ہے.وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ یَّعْمَلُ بَیْنَ یَدَیْہِ بِاِذْنِ رَبِّہٖ(سبا:۱۳)اورجنوں میں سے بھی ایک جماعت اِن کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام میں لگی ہوئی تھی.نیز فرمایا.قَالَ عِفْرِیْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَااٰتِیْکَ بِہٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِکَ (النمل :۴۰) اورجنّوں میں سے ایک نہایت سمجھ دار کار گذار جنّ نے کہا کہ میں آپ کی مطلوبہ شے (ملکہ سباء کا ساتخت) آپ کے اس مقام سے کوچ کرنے سے پہلے حاضرکرسکتاہوں (۱۴)جنّ قرآن کی مثال نہیں بناسکتے فرماتا ہے.قُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا (بنی اسرائیل :۸۹) توکہہ دے کہ اگر انسان او رجنّ مل کر بھی اس قرآن کی مثل بناناچاہیں تونہیں بناسکتے خواہ وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں.
Page 290
جنوں کا آنحضرت ؐ کی مجلس میں حاضر ہونا (۱۵)جنّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اورقرآن سنا.فرماتا ہے.وَ اِذْ صَرَفْنَاۤ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ١ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْۤا اَنْصِتُوْا١ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَ لَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ (الاحقاف :۳۰) اورجبکہ ہم جنوں کی ایک جماعت کو تحریک کرکے تیرے پاس لائے تاکہ وہ قرآن سنیں پھر جب وہ قرآن سنانے کی مجلس میں حاضرہوئے توانہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش(ہوکر قرآن سنو)پھر جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تووہ اپنی قوم کی طرف چلے گئے تاکہ وہ انہیں ہوشیار کریں.سورئہ جنّ میں بھی بیان فرمایا ہے قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا (الجن:۲) میری طرف وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنّوں نے قرآن سنا تو اپنی قوم کو جاکرکہا کہ ہم نے ایک عجیب (پُرلطف) تلاوت سنی ہے (۱۶)جنّات آپؐ پر ایمان لائے.چنانچہ اوپر کی آیت کے بعدہی ان جنّوں کاقول بیان کیا ہے کہ فَاٰمَنَّا بِہٖ ہم اس کلام پر ایمان لے آئے ہیں.یہ وہ مضامین ہیں جو جنات کے متعلق آتے ہیں.قرآن کریم میں جن کا لفظ ارواح خبیثہ پر اور ان وجود وں پر جن کی کفار پوجا کرتے تھے بولا گیا ہے میرے نزدیک ان سے یہ ثابت ہوتاہے کہ جنّ قرآن کریم میں کئی چیزوں کانام رکھا گیا ہے اول جنّ بعض ارواح خبیثہ کانام رکھا گیا ہے.جوشیطانی خیالات کے لئے اسی طرح محرّک ہوتی ہیں.جس طرح کہ ملائکہ نیک تحریکوں کے محرّک ہوتے ہیں.گویا وہ شیطان جو بدی کا محرّک ہے و ہ اس کے اظلال اورمددگار ہیں.یہ مضمون سورۃ الناس کی آیت سے نکلتا ہے جیساکہ فرمایا اَلَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ.(الناس:۶.۷) دوم.ان خیالی وجودوں کانام جنّ رکھا گیا ہے جن کی کافرلوگ پوجاکرتے تھے.ان وجودوں کی تصدیق نہیں کی بلکہ صرف یہ بتایاہے کہ کفار بعض ایسے وجود فرض کرتے ہیں اوران کی پوجا کرتے ہیں اوران کی یہ غلطی ہے.اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدہ کی کہ واقع میں ایسے جنّ ہوتے ہیں تصدیق کرتاہے بلکہ صرف ان کا عقیدہ بیان کرتاہے کہ وہ ایسے وجود مانتے ہیں اوران کی پوجا کرتے ہیں اس کاثبوت سورئہ انعام کی آیت وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَ بَنٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ(الانعام:۱۰۱) یعنے مشرک لوگ جنو ں کو اللہ تعالیٰ کاشریک قرار دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے اوراللہ تعالیٰ کے بیٹے اوربیٹیاں بغیر علم کے تجویز کرتے ہیں.اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ وَخَلَقَھُمْ سے تومعلوم ہوتاہے کہ ایسے جنوں کاوجود ہے اورانہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیاہے.اس کا جواب یہ ہے کہ وَخَلَقَھُمْ حال جَعَلُوْا کی ضمیر کاہے نہ کہ جنوں کا اورمراد یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیدا کیاہے یہ کہتے ہیں کہ جن اللہ تعالیٰ کا شریک کار ہیں.
Page 291
جس قسم کے جن عوام مانتے ہیں ان کا وجود خیالی ہے اس کا ثبوت کہ لوگ جس قسم کے جن مانتے ہیں ان کاوجود خیالی ہے.سورہ سباء کی آیت سے وضاحت سے ملتاہے.فرماتا ہے.وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ۠ اَهٰؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ.قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَوَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ١ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ١ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ.(سبا :۴۱.۴۲)یعنے یادکرو جب اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو جمع کرے گا پھر ملائکہ سے کہے گاکہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے ؟وہ جواب میں کہیں گے کہ تُوپاک ہے اورتُوہی ہمارادوست ہے ان سے ہماراکوئی بھی تعلق نہیں یہ بات غلط ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جنّوں کی پرستش کرتے تھے اوران میں سے اکثر ان پر ایمان لاتے تھے.اللہ تعالیٰ کا ملائکہ کے معبود بنائے جانے کے متعلق ملائکہ سے سوال سوال یہ ہے کہ اگر انسان جنوں کی پرستش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے پوچھاکیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ہستی تو عالم الغیب ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی مشرک بھی فرشتوں کی عبادت نہ کرتاہواوراللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے کہ کیا یہ تمہاری پوجا کرتے تھے نیز اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ کسی جہت سے بھی نہیں کہاجاسکتاکہ لو گ فرشتوں کواُلوہیت کادرجہ دیتے ہیں.توپھر اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے جواب طلب کرنا ظلم بن جاتا ہے.لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَ.اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓىِٕكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ شٰهِدُوْنَ.(الصافات:۱۵۰،۱۵۱)یعنے ان سے پوچھ کہ تمہارے توبیٹے ہیں اوراللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں.کیا اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو مؤنث بنا کر پیدا کیاتھا تویہ لوگ اس وقت موجود تھے.اس آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوںکو مشرک اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اوریہ ظاہر ہے کہ خدا کی بیٹی بھی خدا ہی قرار پائے گی اورقابل پرستش سمجھی جائے گی جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کابیٹا کہاجاتاہے.اورقابل پرستش سمجھاجاتاہے.چنانچہ سورئہ نحل آیت ۵۸ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے شرک کے ذکر میں بیان فرمایا ہے وَیَجْعَلُوْنَ لِلّٰہِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَہٗ اوریہ لوگ اس طرح بھی شرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قراردیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے نقص سے پاک ہے.کفار ملائکہ کی پرستش نہ کرتے تھے بلکہ انہوں نے جنوں یعنی خیالی وجودوں کا نام ملائکہ رکھ لیا خلاصہ یہ کہ اگر مشرک ملائکہ کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں قراردیتے تھے اوراگرکسی کو خدا تعالیٰ کی بیٹی یابیٹاقراردینا شرک ہے توپھر ملائکہ کس طرح کہتے ہیں کہ الٰہی یہ لوگ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے.ان حالات میں اللہ تعالیٰ پر سے اعتراض اٹھ کر فرشتو ں پر اعتراض پڑ جاتاہے.مگرغور کیاجائے تو ان پر بھی اعتراض نہیں پڑتا.کیونکہ اللہ تعالیٰ کاسوال ظاہر پر
Page 292
تھا اورملائکہ کا جواب باطن کو مدنظر رکھ کرہے.مشرک ظاہر میں تویہی کہتے ہیں کہ ملائکہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں.اوران کو خوش کرنا بھی ان کے لئے ضروری ہے لیکن حقیقت تویہی ہے کہ نہ وہ ملائکہ کوجانیں نہ ان کی طاقتوں کویونہی ملائکہ کا ذکر بڑوںسے سن کر ایک خیالی وجود انہوں نے اپنے ذہن میں بنالئے اورخیال کیا کہ یہ ملائکہ ہیں اوراللہ کی بیٹیاں ہیں حالانکہ و ہ وجود محض ذہنی تھے.نہ ملائکہ والے صفات ان میں تھے نہ کام تھے پس درحقیقت ان کی عبادت ملائکہ کے لئے نہ تھی بلکہ چند خیالی اورنظر نہ آنے والے وجودوں کے لئے تھی جنہیں عربی زبان میں جن کہہ سکتے ہیں.ملائکہ کا جواباً یہ کہنا کہ لوگ جنوں کی پوجا کرتے ہیں پس ملائکہ نے جو جواب دیاہے وہ بھی درست ہے.وہ کہتے ہیں کہ الٰہی ہماری انہوں نے کیاپوجاکرنی تھی ہم توتیرے بندے اورتیری حفاظت میں ہیں.یہ توچند ایسے وجودوں کی پرستش کرتے تھے جو محض خیالی اورغیر مرئی ہیں.اگراس قسم کے جنوں کا وجود ہوتاجس قسم کاعوام کہتے ہیں توپھر فرشتوں کایہ قول کہ وہ جنوں کی پرستش کرتے تھے جھوٹ ہو جاتا ہے کیونکہ مشرک یقیناً ملائکہ کو بنات اللہ قرار دے کر ان کی پرستش کرتے تھے اوراسی صورت میں اس پرستش کو جنوں کی پرستش کہاجاسکتاہے کہ جبکہ جنّ کے معنے خیالی اوربناوٹی وجود کے لئے جائیں.اگرکہا جائے کہ وہ جنوں کی بھی پرستش کرتے تھے توگویہ درست ہے کہ بعض وجودوں کی پرستش مشرک جنّ کے نام سے بھی کرتے تھے مگریہاں وہ مراد نہیں ہوسکتی.کیونکہ جنوں کی پرستش سے ملائکہ کی پرستش کی نفی تونہیں ہوجاتی.مشرک توہزاروں قسم کے بت بناتاہے.انسانوں کو بھی خداکہتاہے.سورج چاند کوبھی.دریائوںکو بھی.ملائکہ کو بھی اپنے مزعومہ جنوں کوبھی.پس جنوں کی پرستش کرنے کی وجہ سے ملائکہ کو یہ حق پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی پرستش کا انکارکریں.یہ حق انہیں تبھی پیدا ہوتاہے جبکہ وہ پرستش جو اِن کے نام سے کی جاتی تھی کسی دلیل کی بناء پر کسی خیالی وجود کی طرف منسوب کی جاسکے اوریہی انہوں نے کہا ہے.پس جنّ سے مراد اس آیت میں خیالی اورذہنی وجود کے ہیں جن کانام کفار نے ملائکہ رکھ لیاتھا مگر فی الواقع وہ ملائکہ نہ تھے.جن کا لفظ ان اقوام کے لئے بھی بولا جا تا ہے جو شمالی سرد علاقوں میں رہتی ہیں جن چونکہ مخفی وجود کو کہتے ہیں اس لئے جن کالفظ قرآن کریم میںعربوں اوردوسری اقوام کے محاورہ کے مطابق ان اقوام کے لئے بھی بولاجاتاہے جوشمالی علاقوں میں اورسرد ممالک میں رہتی تھیں.چونکہ لوگ بوجہ شدت سردی کے ان کے ممالک کی طرف سفر نہیں کرتے تھے.اوروہ گرمی کی وجہ سے ادھر نہ آتے تھے.نیز چونکہ سرد علاقوں میں رہنے کے سبب سے وہ زیادہ سفید رنگ والے اورشراب کے استعمال کی وجہ سے زیادہ سرخ ہوتے تھے ایشیا کے لو گ انہیں کو ئی الگ قسم کی
Page 293
مخلوق سمجھتے تھے.اورانہیں جن اورپریاں کہتے تھے یہ ان کاعام نام تھا.یہود کا خیال کہ جن شمالی علاقہ میں رہتے ہیں چنانچہ جیساکہ میں اوپر لکھ آیاہوں یہود کایہ عقیدہ تھا کہ جنّ شمالی علاقہ میں رہتے ہیں.چنانچہ شرکی ربیّ الیعذرنے اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے کہ جنّ زیادہ تردنیا کے شمالی علاقوں میں رہتے ہیں.ہندوؤں نے بھی جنوں کا مقام شمال میں تجویز کیا ہے ہندوقو م نے بھی اپنے شمال میں ہی جنّوں کا مقام تجویز کیا ہے.چنانچہ جیسا کہ حوالہ گذر چکا ہے ہندوئوں کے نزدیک گندھروا لوگوںکاعلاقہ ہندوستان کے شمال مغرب میں تھااورٹیکسلا شہر جوعلاقہ ہزارہ میں تھا اسے وہ گندھروا کے علاقہ کا شہر کہتے تھے.اوردریائے سندھ کے شمال کے علاقہ کو ان کامسکن قرار دیتے تھے.یعنی ہزارہ افغانستان وغیرہ کو.مسلمانوں میں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں ان میں بھی جنّات کامسکن کوہ قاف اوراس کے پار کا علاقہ سمجھاجاتاہے.شمالی علاقہ کے لوگوں کو جن کہے جانے کی وجہ پس یہ بات ظاہر ہے کہ شمالی علاقوں کے سرخ و سفید لوگ جو تمدّنی حالات کے ماتحت قریباً ایشیا سے بالکل الگ ہوگئے تھے اوربہت کم ادھر آتے تھے اورمذہب اورطورطریق کے لحاظ سے بھی الگ تھے.ایشیا کے رہنے والوں کے نزدیک جواس وقت تمدن کے حامل تھے جنّ تھے.کیابلحاظ اپنی شکلوں کے اور کیا بلحاظ ایشیاسے دوررہنے کے (شائد ہندوئوں نے نہ صرف شمال مغربی علاقہ کے ساکنوں کی ظاہری شکل کی وجہ سے بلکہ ان کی قوت اورطاقت کی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ ہندوستان پر حملہ کرتے رہتے تھے ان کو جنّ قرار دیا).سورۃ رحمٰن میں شمالی لوگوں کو جن کہا گیا ہے اسی محاورہ کے مطابق قرآن کریم میں بھی سورئہ رحمن میں ان شمالی لوگوں کویعنی یورپ کے باشندوں کو جنّ کہا ہے.اس سورۃ میں آخر ی زمانہ کے تغیرات کا ذکر ہے اوربتایا گیا ہے کہ اس وقت دومشرق اوردومغرب ہوجائیں گے یعنی امریکہ کی دریافت سے دو علاقے مشرق اوردو مغرب کہلانے لگیں گے.اسی طرح نہر سویزکے ذریعہ دوسمندروں کے ملنے اوربڑے بڑے جہازوں کے چلنے کی خبردی گئی ہے اسی طرح بتایا ہے کہ اس وقت سائینس کی ترقی کے ساتھ لو گ آسمانی بادشاہت کو فتح کرنے کے خیال میں مشغول ہوں گے اورسمجھیں گے کہ وہ جلد کائنات کاراز دریافت کرنے والے ہیں.اس وقت آسمان سے آگ گرے گی اوربم گریں گے اورسرخ روشنیاں آسمان پر چھوڑی جائیں گی اورآخر کفر اورشرک کو تباہ کرکے اسلام کو غلبہ دیاجائے گا.اس مضمون کے سلسلہ میں جنّ و انس کو بھی مخاطب کیاگیا ہے اورجنّ سے مراد وہی شمالی علاقوں کے لوگ یعنی یورپین
Page 294
مراد ہیں اوربتایا ہے کہ اس زمانہ میں یورپ اورایشیا کے لوگ باہم مل جائیں گے.اورسائنس کی بڑی ترقی ہوگی.مگر بے دینی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرےگا اورپھر اسلام کو قائم کرے گا.جن اور الناس سے مراد ڈیماکرسی اور ڈکٹیٹرشپ ثقلان اورجنّ اورالناس سے مراد ڈیما کرسی اور ڈکٹیٹروں کی حکومت بھی ہوسکتی ہے.کیونکہ جنّ کے معنے عربی لغت میں اکثریت کے بھی ہیں اورالناس کے معنے خاص آدمیوں کے بھی ہوسکتے ہیں(اقرب).پس جنّ سے مراد ڈیما کرسی ہے.اورالناس سے مراد وہ لوگ ہیں جواپنے آپ کو خاص قرار دے کر حکومت کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں.ثقل کے معنے اعلیٰ اورمحفوظ شے کے ہوتے ہیں.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اوراپنی اولاد کو ثقلان قراردیاہے.پس الثقلان سے مراد یہ دونوں گروہ ہیں جو اس وقت ساری دنیا پر غالب ہوں گے بعض ڈیماکرسی کے نام پر دنیاکومغلوب کریںگے اوربعض فاشزم اورناٹزم کے نام پردنیا کو سمیٹنا چاہیں گے.اور اپنے آپ کو سب دنیا سے بہتر قرار دیں گے.قرآن مجید میں غیر قوموں اور غیر مذاہب کے لئے لوگوں کے جن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے علاو ہ قرآن کریم میں غیرقوموں اورغیر مذاہب کے لوگوں کے لئے بھی جنّ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں.مثلاً حضرت سلیمان کے ذکر میں جہاں جنّوں کا ذکرہے اس سے مراد غیر قوموں کے لوگ ہی ہیں.چنانچہ اللہ تعالیٰ ان جنوں کی نسبت فرماتا ہے کہ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَ تَمَاثِيْلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَ قُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ (سبا:۱۴) وہ جنّ حضرت سلیمان ؑ کے لئے دربار کاکمرہ مسجد کامحراب اورمحل بناتے تھے اورمجسمے اوربڑے بڑے حوض جو کنوئوں کی طرح تھے او ر بہت بڑی بڑی دیگیں تیارکرتے تھے.اب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کام حضرت سلیمان کے لئے کس نے کئے ہیں.توہمیں ۲تواریخ باب۲.۷ میں لکھا ملتاہے کہ جب حضرت سلیمان نے بڑی عبادت گاہ تعمیر کرنے کااراد ہ کیا.توآپ نے صورکے بادشاہ کو خط لکھا کہ اپنے انجنیئروں میں سے میرے پاس ایک انجینئر بھجوائو’’جو سونے اورروپے اورپیتل اورلوہے اورارغوانی اورقرمزی اورآسمانی رنگوں کے کاموں میں ہوشیار اورنقاشی میں دانشمند ہو.‘‘اسی طرح لکھا کہ وہاں کی لکڑی بھجوائو اورمیں لکڑی کاٹنے والوں کو اس اس قدر مزدوری دوں گا.آیت ۱۰.پھر آیت ۱۴ میں صورکے بادشاہ کا جواب ہے کہ ا س نے حضرت سلیمان کے کہنے پر ایک انجینئر حورام ابی نامی بھجوایا اورکہا کہ یہ سب فنون کاماہر ہے.اورلکھا کہ لکڑی کاٹنے پر میں نے آدمی لگادیئے ہیں.ان کی مزدوری بھجوادیں.آیت ۱۵.یہ تو غیر ملکی انجنئیرکا ذکرہے.جو مزدور لگائے گئے ان کایوں ذکرآتاہے.’’اورسلیمان نے اسرائیل کے ملک میں سارے پردیسیوںکو گنوایا بعد اس گننے کے جو اس کے باپ دائود نے
Page 295
گنوایاتھا اوروے ایک لاکھ ترپن ہزار چھ سوٹھہرے.اوراس نے ان میں سے ستر ہزارکو باربرداری پر اوراسی ہزار کو پہاڑ کے توڑنے پر مقرر کیا اوران پر تین ہزار اوورسیر مقرر کئے.کہ ان لوگوں سے کام لیویں.‘‘آیت ۱۷و۱۸.ان آیات سے ظاہر ہے کہ مزدوری پر بھی غیرقوموں کے لو گ مقرر کئے گئے تھے.اب جوکام اس صور کے انجینئر نے کیا.وہ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑاہال عبادت کے لئے بنایا.(محاریب)اوربڑے ہال کے اندرفرشتوں کے مجسمے دیواروں کے اند رکھود کر بنائے اوراسی طرح بڑے ہال میں بھی دوفرشتوں کے مجسمے تراش کر بنائے.(تمثَال)( ۲تواریخ باب۳ آیت ۷و ۱۰ تا ۱۳)اورپھر باب ۴ آیت ۲و ۶ میں بتایا ہے کہ ایک بڑا حوض بنایا جودھاتوں سے ڈھالاہواتھا.اوراس کے علاو ہ دس چھوٹے حوض بنائے (جِفَانٍ کَالْجَوَابِ)پھر اسی باب۴ کی آیت۱۵.۱۶ میں لکھا ہے کہ حورام انجینئر نے جو باہر سے آیاتھا.‘‘ اورایک بحر ( لفظی معنی سمند ر مراد بڑاحوض)اوراس کے نیچے بارہ بیل اوردیگیں اورپہاوڑے اورکانٹے اورسب ظروف جو حورام ابی نے سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر کے لئے بنائے صاف پھول دھات کے تھے.‘‘اس ایک آیت میں دیگوں(قُدُوْررَاسِیٰتٍ)حوضوں اورمجسموں کا ذکر اکٹھا آگیاہے.حضرت سلیمان کی خدمت کرنے والے غیر ملکی اور غیر قوم کے لوگ تھے جن کو جنّ کہا گیا ہے غرض و ہ سب اشیاء جن کا ذکر اس آیت میں آیاہے حضرت سلیمان نے حورام ابی سے جو ایک غیر ملکی انجینئر تھا اورغیر ملکی مزدوروں سے بنوائی تھیں.پس جنّ سے مراد محض غیر ملکی اورغیرقوم کے لوگ ہیں.جن کو حضرت سلیما ن کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی.صرف رُعب خداداد کی وجہ سے وہ آپ کے تصرف کے نیچے آئے ہوئے تھے اور آپ کاکام کرتے تھے جب آپ فوت ہوگئے.توکچھ مدت تک تو آپ کی حکومت کارعب ان لوگوں کے دلوں پر رہا.جب آپ کے لڑکے نے بعض نالائقیوں کی وجہ سے اس رعب کوضائع کردیا.تو وہ لوگ پچھتائے کہ خوامخواہ ان کے لئے لکڑیا ں ڈھونے اور دوسرے ذلیل کاموں میں ہم کیوں لگے رہے ؟اوریہ ذلّت برداشت کی اگریہ حکومت اتنی جلدی فناہوجانی تھی.توہم مقابلہ جاری رکھتے.حضرت آدم ؑ کے زمانہ کے لوگوں کا نام قرآن کریم میں جن رکھا گیا ہے چوتھا استعمال جنّ کے لفظ کاقرآن کریم میں ان لوگوں کے متعلق ہے.جو حضرت آدم کے زمانہ میں دنیا پر بستے تھے اورجن میں سے نکل کر حضرت آدم نے ایک نیا نظام قائم کیا تھا.چونکہ آدم نظام کاقائم کرنے والاپہلا شخص تھا.اس سے پہلے لوگ نظام کی قدرکو نہ جانتے تھے.اورجانوروں کی طرح الگ الگ درختوں کی جڑوں میں یاغاروں میں رہتے تھے.اورجنگلی
Page 296
درندوں کی وجہ سے سطح زمین پر آسانی سے چل پھر نہیں سکتے تھے.ان کانام ان کی حالت کے مطابق جنّ رکھا گیا ہے.یہ وہی لوگ ہیں جن کو آجکل کے مؤرّخ CAVEMAN کہتے ہیں.یعنی کھوہوں اور غاروں میں رہنے والے لوگ جو سطح زمین پر بودوباش نہ کرتے تھے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ CAVE).جب انسانی دماغ نے ترقی کی اورانسان الہام کی نعمت کے قبول کرنے کے قابل ہوگیا.تواللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جسے اس نے آدم کاخطاب دیا کیونکہ وہ سطح زمین پر رہنے کے قابل ہوگیاتھا اورانسان کاخطاب دیا.کیونکہ وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے قابل ہوگیا تھاتودوسری طرف بنی نوع کے ساتھ ہمدردی کرنے اوران کے لئے قربانی کرنے کے قابل تھا.اپنے الہام کے لئے چنا (دیکھو تفصیلی دلائل کے لئے میری کتاب سیر روحانی جلد اول) جنہوں نے اس کے نظام کو قبول کیا اوراس کے ساتھ مل گئے اورباہر نکل کر مکان وغیرہ بنانے لگے اور تمدّنی قوانین کی پابندی کو منظورکرلیا وہ آدمی کہلائے.لیکن جنہوں نے وحشت کی زندگی کو ترک کرنے سے انکار کردیا.اورغاروں کی زندگی کو حریّت قرار دیا.ان کانام ان کے طرز رہائش کی وجہ سے جنّ قرار پایا پس جنّ بشری ترقی کے دو ر کے اس حصہ کے افراد کانام ہے.جوتمدن سے عار ی تھے.اورنظام کوقبول کرنے کے ناقابل تھے.اورآدمی بشری ترقی کے دورکے اس حصہ کانا م ہے جس میں ایک جماعت نے مل کر رہنے اورایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اورایک نظام کی پابندی کا اقرار کیا.آئندہ کے لئے یہ دونام ان دوصفات کے ساتھ وابستہ ہوگئے اورجو لوگ نظام کے باغی ہوں.ان کانام جنوں کی ذریت رکھا گیا.اورجو نظام کے تابع ہوں ان کانام آدم کی ذریت رکھا گیا.اب یہ دونوں نام صفاتی ہیں جس کی وجہ سے کبھی جنوں کی اولاد اصلاح کر کے آدمی ہوجاتی ہے اور کبھی آدمیوں یعنے پابندِ نظام لوگوں کی اولاد گندی اورنظام شکن ہوکر جنّ بن جاتی ہے.رسول کریم کے زمانہ میں ایمان لانے والے دراصل یہودی تھے اب رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا سوال کہ اس وقت جو جنّ ایمان لائے تھے وہ کیسی مخلوق تھی.سو اس کے متعلق قرآن کریم سے ثابت ہے کہ وہ یہودی تھے کیونکہ وہ موسیٰ کی کتاب کا اوراس پر ایمان لانے کا ذکرکرتے ہیں.پس معلوم ہواکہ وہ یہودی لوگ تھے (الاحقاف :۳۰.۳۱).اللہ تعالیٰ نے ان کو جنّ اس لئے کہا ہے کہ وہ باہر کے لوگ تھے.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی ملے تھے.آنحضرت ؐ پر ایمان لانے والے جن نصیبین کے رہنے والے تھے اور رات کو آپ ؐ سے ملے تھے بعض احادیث سے معلوم ہوتاہے کہ وہ نصیبین کے رہنے والے تھے اوررات کےوقت رسول کریم
Page 297
صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے (بخاری کتاب مناقب الانصار ذکر الجن و قولہ قل اوحی...) واپس جاکر جو واقعہ ان کے اوران کی قوم کے درمیان گذرا.اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے.معلوم ہوتا ہے عرب لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے چھپ کررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیار ت کی اورآپؐ سے قرآن سنا.جب واپس ہوئے.تودلوں نے گواہی دی کہ آپ سچے ہیں.اوراپنی قوم میں تبلیغ شروع کردی.مومن جنّوں کے انسان ہونے کے سات ثبوت اس امر کاثبوت کہ یہ جنّ انسان تھے مندرجہ ذیل ہے.اول یہ کہ وہ پوشیدہ ملے.اگر وہ جنّ تھے.توان کو پوشیدہ اوررات کو ملنے کیاضرورت تھی علی الاعلان ملتے.توکوئی ان کاکیابگاڑ سکتاتھا.اورجنّوں کی جوشان بیان کی جاتی ہے.ا س کے لحاظ سے انہیں دیکھ بھی کون سکتا تھا.دوسراثبوت دوم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ(الفتح :۱۰) یعنی مومنو! ہم نے یہ رسول ا س لئے بھیجا ہے کہ تم اس کی مدد اور نصرت کرو.اورا س کی عزت دنیا میں قائم کرو.اگر جنات ایمان لائے تھے.تووہ کس رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے.کہتے ہیں کہ جنّ لوگوں کے سروں پر چڑھ جاتے ہیں.اورقسم قسم کے پھل لاکردےدیتے ہیں.اگر جن کوئی مخفی مخلوق تھے انہوں نے آنحضرت ؐ کی مدد کیوں نہ کی؟ یہ کیسے مومن تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم پر ظلم ٹوٹا.لیکن کافر جنّوں نے تو حضر ت سلیمان کے لئے قلعے تیار کئے اورہر ذلیل سے ذلیل کام ان کی خاطر کیا.یہ مومن ایسے طوطاچشم تھے کہ ابوجہل وغیرہ کسی کو انہوں نے سزا نہ دی.اورپھر یہ جنّ لوگوںکو توبے موسم کے پھل لاکر دے دیتے ہیں.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر انہیں یہ توفیق بھی نہ ملی جب غزوہ خندق کے موقعہ پر آپؐ پر اور دوسرے مسلمانوں پر فاقے پر فاقے آرہے تھے.اورآپؐ اورآپؐ کے صحابہ گویاپیٹوں پر پتھر باندھے پھر رہے تھے(بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ خندق).یہ لوگ آپؐ کے لئے اور آپؐ کے صحابہ کے لئے جَوکی روٹیاں ہی لادیتے.یہ توایما ن کی علامت نہیں بلکہ اول درجہ کی شقاو ت کی علامت ہے.لیکن قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ وہ ایماندار مخلص تھے.پس ظاہر ہے کہ نہ ان جنّوںکو جن کا ذکر سورئہ جنّ میں ہے طاقت ہے کہ کسی کے سرپر چڑھیں اورانسانوں پر قبضہ کر سکیں یاانہیں ستاسکیں اور نہ ان میں کسی کو کچھ لاکردینے کی طاقت ہے.ایسے جنّ صر ف وہمی لوگوں کے دماغ میں ہیں قرآن کریم ایسے جنّوں کو تسلیم نہیں کرتا.اس نے تو جو جنّ پیش کئے ہیں انہی اقسام کے ہیں جو میں نے بیان کئے.اوران اقسام میں سے جو جنّ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ یہودی تھے جنہوں نے کلام سنا اپنے گھروں کو چلے گئے.اورآخر ایمان لانے کافیصلہ کیا اوراپنی
Page 298
قوم کو پیغام پہنچادیا.عرب سے ہزاروں میل دور کے بسنے والے تھے.بعد میں نہیں کہا جاسکتا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کو ئی خبر ملی بھی یانہیں ملی.اس وجہ سے وہ اسلامی جنگوں میں عملاً کوئی حصہ نہ لے سکے.تیسرا ثبوت تیسراثبوت اس امر کا کہ یہ جنّ انسان تھے یہ ہے.کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے متعلق فرماتا ہے کہ وہ مِنْ اَنْفُسِہِمْ اورمِنْہُمْ ہوتے ہیں یعنی جن کی طرف آتے ہیں انہی کی قوم کے ہوتے ہیں.چنانچہ فرماتا ہے.وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰؤُلَآءِ(النحل :۹۰)یعنی قیامت کے دن ہر امت کارسول جوانہی میں سے ہوگا بطورگواہ لایاجائے گا.اورمحمدؐ رسو ل اللہ کو امت محمدیہؐ اوراس زمانہ کے لوگوںپر بطور گواہ بھیجاجائے گا.اگر جنّ بھی کوئی ایسی قو م ہے.جوایمان لاتی ہے.توا س پر گواہی کو ن دے گا؟موسیٰ توجنّ نہیں کہ ان جنّوں کے متعلق ان سے پوچھا جائے گاجو ان پر ایمان لائے تھے.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے.وہ جنّوں سے من انفسہم کی نسبت نہیں رکھتے.پس آپ جنّوں کے متعلق شہید نہیں ہوسکتے.من انفسہم سے مراد پہلے انبیاء کی نسبت سےان کی اقوام ہیں.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے زمانہ کے بعدکے سب انسان.پس جنّ اگر کو ئی انسانوں جیسی مکلّف مخلوق ہے تووہ یونہی رہ جاتے ہیں.نہ ثواب کے مستحق نہ عذاب کے.چوتھا ثبوت چوتھا ثبوت اس دعویٰ کی تائید میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ۠ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا(الانعام :۱۳۱)یعنے اے جنّوں اورانسانوں کی جماعتو! کیاتمہارے پاس تمہاری قوموں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میرے نشانات پڑھ کرسناتے تھے.اورآج کے دن کے دیکھنے سے تم کو ہوشیارکرتے تھے ؟ا س آیت میں صاف لکھا ہے کہ جنوں کی طرف ان کی قوم کے نبی آئے اورانسانوں کی طرف انسان نبی.اب اگر جنّ کوئی دوسری مخلوق ہے تواس آیت کے ماتحت نہ توموسیٰ ان کے نبی ہوسکتے ہیں.نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.کیونکہ جنوں کی طر ف اس آیت کے ماتحت جنّ نبی ہی آئے تھے.ہاں! اگرجنّوں سے انسانوں کاکوئی گروہ مراد ہو.توپھر بے شک وہ موسیٰ ؑ اورآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن ہوسکتے ہیں.پانچواں ثبوت پانچواں ثبوت ا س امر کاکہ عوام میں جو جنّ مشہور ہیں ان کاکوئی وجود نہیں.اوریہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنّ ایمان لائے تھے وہ انسان ہی تھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی نسبت فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ (البقرۃ :۲۵) دوزخ میں یاتو انسان ہوں گے یا پھر پتھر وغیرہ آگ کو بھڑکانے
Page 300
نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کاایک واقعہ انجیل میں بیا ن ہواہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسری اقوام کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت تک نہ دی بلکہ جب ان سے ایک غیر قوم کے آدمی نے تبلیغ کرنے کے لئے کہا.توآپ نے فرمایا’’کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینی اچھی نہیں‘‘(متی باب ۱۵آیت ۲۶)پس یہ بھی درست نہیں.کہ وہ اپنی مرضی سے ایمان لے آئے تھے.کیونکہ اگر جن کو ئی مکلف قوم ہے.توا س کے لئے صرف اس نبی پر ایمان لانا فرض ہے جو مِن انفسہم ہو.موسیٰ علیہ السلام پر ایما ن لانا ان کے لئے جائز نہ تھا.غرض قرآن کریم کی آیات اور مذکورہ حدیث کے رُو سے کم سے کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنوں کے لئے الگ نبی مبعوث ہونے ضروری تھے.جو خود ان میں سے ہوتے.نیز جنوں کی مختلف قوموں کی طرف الگ الگ نبی مبعوث ہونے ضروری تھے.مومن جنات کے انسان ہونے کی ساتویں دلیل ساتواں ثبوت ان جنات کے انسان ہونے کایہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کادعویٰ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے.یٰٓااَیُّھَاالنَّاسُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا.(الاعراف :۱۵۹) آنحضرت ؐ کا دعویٰ صرف انسانوں کی طرف مبعوث ہونے کا تھا اس جگہ جنوں کو رسالت میں شامل نہیں کیا.اگرجن بھی کو ئی علیحدہ قوم ہے.اوراس کے لئے بھی آپ پر ایما ن لا نا ضروری تھا یاجائز ہی تھا.تویوں فرماناچاہیے تھاکہ یٰٓااَیُّھَاالنَّاسُ وَالْجِنُّ اِنِّی رَسُوْ لُ اللہِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا مگر یہ تو قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں آیا پس جو جن آپؐ پر ایمان لائے وہ قرآنی تشریح کے ماتحت انسانوں ہی میں سے تھے.اوراسی وجہ سے آپؐ پر ایمان لانے کے مکلف تھے.ایک اورآیت اس مضمون کے بارہ میں اس سے بھی واضح ہے.اوروہ سورئہ سبا کی آیت وَمَااَرْسَلْنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ ہے (سبا : ۲۹) کَافَّۃ کَفَّ سے نکلا ہے جس کے اصل معنے جمع کرنے اورروکنے کے ہیں.پس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے صرف اس لئے مبعوث کیا ہے.کہ تو انسانوں کو جمع کرے اور کسی انسان کو اپنی تبلیغ سے باہر نہ رہنے دے.اب دیکھو! اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تجھے صرف انسانوں کوجمع کرنے کے لئے بھیجا ہے.اوربعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ انسانوں کے سواکوئی اورمخلوق بھی ہے اوروہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی مکلف ہے.پس حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں سے کوئی آپ کی دعوت سے باہر نہیں انسانوں کے سوا کوئی مخلوق آپ پر ایمان لانے کے لئے مکلف بھی نہیں.اس وجہ سے جن مومن جنّوں کا ذکر
Page 301
قرآن کریم میں کیاگیاہے.وہ انسان ہی تھے کوئی اورمخلوق نہ تھے.قرآن کریم میں لفظ جن کا استعمال خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم میں جنّ کئی معنوں میں استعمال ہواہے.جنّ کے لفظ کا استعمال مخفی اور غیر مرئی مخلوق کے لئے (۱)جنّ وہ تمام مخفی مخلوق جو غیر مرئی شیطان کی قسم سے ہے یہ مخلوق اسی طرح بدی کی تحریک کرتی ہے جس طرح ملائکہ نیک تحریکات کرتے ہیں.ہاں یہ فرق ہے.کہ ملائکہ کی تحریک وسیع ہوتی ہے اوران کی تحریک محدود ہوتی ہے.یعنی ان کو زور انہی پر حاصل ہوتا ہے جوخود اپنی مرضی سے بدخیالات کی طرف جھک جائیں.انہیں شیاطین بھی کہتے ہیں.جنّ سے مراد زیر زمین رہنے والے (۲)جنّ سے مراد قرآن کریم میں CAVE MEN بھی ہے.یعنے انسان کے قابل الہام ہونے سے پہلے جو بشر زیر زمین رہاکرتے تھے.اور کسی نظام کے پابند نہ تھے.ہاں آئندہ کے لئے قرآن کریم نے یہ اصطلاح قراردے لی.جولوگ اطاعت کامادہ رکھتے ہیں.ان کانام انسان رکھا.اورجو لوگ ناری طبیعت کے ہیں اوراطاعت سے گریز کرتے ہیں ان کانام جنّ رکھا.جنّ سے مراد شمالی علاقہ کے لوگ (۳)شمالی علاقوں کے وہ لوگ یعنے یورپ وغیرہ کے جو ایشیا کے لوگوں سے میل ملاپ نہ رکھتے تھے.اورجن کے لئے آخر زمانہ میں حیرت انگیز دنیوی ترقی اورمذہب سے بغاوت مقدر تھی.ان کا ذکر سورئہ رحمٰن میں کیا ہے.غیر مذاہب کے لوگوں اور اجنبیوں کے لئے لفظ جن کا استعمال (۴)غیر مذہب کے لوگوں کو اوراجنبیوں کو جنہیں بعض اقوام جیسے ہندو اوریہودکوئی نئی مخلوق سمجھتے تھے.ان کو عام محاورہ کے مطابق پر جنّ کے نام سے موسوم کیا ہے جیسے حضرت سلیمان کے جنّ یارسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لانے والے لوگ.میرے نزدیک دوزخ میں جانے والے جن جنّات کا ذکر آتا ہے ان سے مراد یاتووہی ناری طبیعت والے لوگ ہیں جواطاعت سے باہر رہتے ہیں.اور کسی مذہب یاتعلیم کو قبول نہیں کرتے.اورانسان دوزخیوں سے مراد وہ کفار ہیں جو کسی نہ کسی مذہب سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں.یاپھر اقوام شمال مغرب کو جنّ قرار دیا ہے اورجنوبی دنیا اورمشرق کے لوگوں کو اِنس قراردیا ہے.جیساکہ عرف عام میں یہ لوگ ان ناموں سے مشہور تھے.یہ جو فرمایاکہ وَ الْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم جنّ کہتے ہیں.ان کی طبیعت میں ناری مادہ تھا یعنے جلد اشتعال میں آجاتے تھے اوراطاعت برداشت نہیں کرسکتے تھے.حضرت آدم سے پہلے بشر کی حالت یہی تھی.حضرت آدم پہلے انسان تھے.جنہوں نے اخلاقی اور تمدنی کمال حاصل کیا.اس وجہ
Page 302
سے الہام جس کاتعلق تمدن اوراخلاق سے ہے سب سے پہلے آپ ہی پر نازل ہوا.پس جو لوگ اس تمدن اورنظام میں شامل ہوئے انہوں نے گویا اپنے نفسوں کو ما ر دیا.اوراللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نقش اپنے دلوں پر کندہ کروالیا.پس وہ طینی کہلائے.کیونکہ طین نقش قبول کرتی ہے.اورجن لوگوں نے نظام میں آنے کی نسبت انفرادی آزادی کو مقد م رکھا اور کسی کی اطاعت کا جواگردن پر رکھنے سے انکار کیا وہ ناری کہلائے.یعنی جس طرح آگ کاشعلہ قابو میں نہیں آتا.اسی طرح وہ بے قابو ہوگئے.اوربوجہ زمین کے اندر رہنے کے وہ جنّ بھی کہلائے.جنوں کے آگ سے پیدا ہونے سے مراد ناری طبیعت اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ توفرماتا ہے خَلَقْنٰہُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ.جنوں کو آگ سے بنایا.پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ اس سے مراد ناری طبیعت ہے ؟تواس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے.خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ (الانبیاء:۳۸) جس کے لفظی معنے ہیں انسان کو (اللہ تعالیٰ نے)جلدی سے پیدا کیا.محقق مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کامطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں عجلت اورجلدبازی ہے یہ نہیں کہ جلدی نام کسی مادہ کا ہے جس سے انسان کو بنایاگیاہے.اوروہ لکھتے ہیں کہ یہ عربی کاعام محاورہ ہے کہ جوشے کسی کی طبیعت میں داخل ہو.اس کے بارہ میں کہتے ہیں کہ وہ اس سے پیدا کیاگیاہے.ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اَللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ ضُعْفٍ(الروم:۵۵)یعنے خدا تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ تمہاری طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے.یعنی پیدائش کے وقت بچہ کمزورہوتاہے اور دوسرے کی امداد کا محتاج ہوتاہے.ا س آیت کے بھی یہ معنی نہیں کہ ضعف کوئی مٹی یالکڑی کی قسم کی شے ہے جس سے خدا تعالیٰ نے انسان کو بنایاہے.جنات کا انسانوں پر غلبہ پانا غلط ہے یہ تعلیق ختم کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتادینا چاہتاہوں کہ کئی پرانے بزرگ کم سے کم اس خیال میں میرے ساتھ شریک ہیں.کہ وہ جنّ کوئی نہیں ہوتے جو انسانوں سے آکر ملیںاوراس پر سوا ر ہوجائیں اوران سے مختلف کام لیں.چنانچہ علامہ ابن حیّان اپنی تفسیر بحرمحیط کی جلد پانچ ص ۴۵۴ پر لکھتے ہیں.کہ جبائی کاقول ہے.کہ یہ آیت (اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ جوآیت زیر تفسیر کے چند آیات بعد ہی ہے ) ان لوگوں کے دعووں کو رد کردیتی ہے.جن کایہ خیال ہے کہ شیطان اورجنّوںکے لئے ممکن ہے کہ انسانوں پر غلبہ پالیں.اوران کی عقلوں کو خراب کردیں.جیساکہ عام لوگوں کا عقیدہ ہے.اوربعض دفعہ عوام ان امو ر کو جادوگروں کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں.اوریہ سب دعوے اللہ تعالیٰ کی نصّ صریح کے خلاف ہیں.اگرکہا جائے کہ بعض بزرگوں نے جنات کا ذکر کیا ہے.تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ روحانی نظارے ہیں
Page 303
اورعالمِ مثال میں ایسی باتیں نظر آجاتی ہیں.انہوں نے کشف سے بعض امور دیکھے.اور چونکہ عوام میں جنّات کا عقیدہ تھا اورقرآن کریم میں بھی لفظ جنّ کااستعمال ہواہے انہوں نے ان مثالی وجودوںکو اصلی وجود سمجھ لیا.جنات کے متعلق اپنا ذاتی تجربہ میرااپنا ذاتی تجر بہ اس بارہ میں یہ ہے کہ کئی مختلف وقتوں میں لوگوں نے مجھے ایسے خطوط لکھے ہیں.کہ جنّات ان کے گھر میں آتے اورفساد کرتے ہیں.میں نے ہمیشہ اپنے خرچ پر ا س مکان کا تجربہ کرناچاہا.لیکن ہمیشہ ہی یاتویہ جواب ملا کہ اب ان کی آمد بندہوگئی ہے.یایہ کہ آپ کے خط آنے یا آپ کاآدمی آنے کی برکت سے وہ بھاگ گئے ہیں.میرااپنا خیال ہے کہ جوکچھ ان لوگوں نے دیکھا ایک اعصابی کرشمہ تھا.میرے خط یا پیغامبرسے چونکہ انہیں تسلی ہوئی وہ حالت بدل گئی.اگر اس تفسیر کے پڑھنے والوں میں سے کسی صاحب کو اس مخلوق کاتجربہ ہو.اوروہ مجھے لکھیں.تومیں اپنے خرچ پر اب بھی تجربہ کرانے کوتیارہوں.ورنہ جوکچھ میں متعدد قرآنی دلائل سے سمجھا ہوں یہی ہے کہ عوام الناس میں جو جنّ مشہور ہیں اورجن کی نسبت کہا جاتاہے کہ وہ انسانوں سے تعلق رکھتے اوران کو چیزیں لاکردیتے ہیں.یہ محض خیال اوروہم ہے.یامداریوں کے تماشے ہیں جن کے اندرونی بھید کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں نے ان کو جنّات کی طرف منسوب کردیاہے.اس علم کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے.اوربہت سی باتیں ان ہتھکنڈے کرنے والوں کی جانتاہوں.ہاں! یہ میں مانتاہوں.کہ ممکن ہے پہلے انسان ناری وجود ہو.اورزمانہ کے تغیرات سے بدلتے بدلتے ارتقاء کے ماتحت طینی وجود ہوگیا ہو.یعنی اس کی بناو ٹ کی بنیاد زمینی پیداوار پر آگئی ہو.اورایسے وجود جو سب سے پہلے تیارہوئے.ان کاسردار آدم ہو یہ کوئی بعید بات نہیں.علم جیالوجی سے یہ امر ثابت ہے کہ دنیا میں مٹی کاچھلکا بعد میں بنا ہے پہلے دنیا ایک گرم آگ کا کرّہ تھی.سو ارتقاء کے لحاظ سے اگر طینی ابتدا سے پہلے انسان کی ابتدا ناری وجود سے تسلیم کی جائے تومستبعد نہیں.مگریہ امور تخمینی ہیں.ان کو یقین سے بیان نہیں کیاجاسکتا.اس لئے میں نے اس کے متعلق زیادہ نہیں لکھا.اس مضمون کا کچھ حصہ قصہ آدم اورشیطان سے بھی حل ہوگا.اس کے لئے سورہ بقرہ میں قصہ آدم کاموقعہ دیکھنا چاہیے.
Page 304
وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ۠ اِنِّيْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ اور(اے مخاطب اس وقت کو یاد کر)جب تیرے رب نے فرشتوں کو فرمایاتھا(کہ)میں یقینا ً آوازدینے والی مٹی مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ۰۰۲۹فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ یعنی سیاہ گار ے سے جس کیہیئت تبدیل ہوچکی ہوایک بشر پیداکرنے والاہوں.پس جب میں اسے مکمل کردوں رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ۰۰۳۰ اوراس (کے دل)میں اپنا کچھ کلا م ڈال دوں.توتم سب اس کےساتھ سجدہ کرتے ہوئے (اللہ کے حضور)گرجانا.حلّ لُغَات.سَوّیْتُہٗ.سَوَّیْتُہُ سَوَّی سے متکلم کا صیغہ ہے اورسَوَّی الشَّیْءَ کے معنی ہیں.جَعَلَہٗ سَوِیًّا اس کو سویّ یعنی بے عیب وبے نقص بنادیا.غُلَامٌ سَوِیٌّ.اَیْ لَادَاءَ بِہٖ وَلَا عَیْبَ.جب یہ لفظ انسان کے لئے بولاجائے.تواس کے معنے ہوتے ہیں کہ جسمانی طورپر بھی اس میں کوئی نقص نہیں ہے اوراخلاقی لحاظ سے بھی اس میں نقص نہیں ہے.چنانچہ غلامٌ سویٌّ ٌّ ایسے لڑکے پر بولتے ہیں جس میں اخلاقی اور جسمانی کوئی نقص اورعیب نہ ہو.وَمِنْہُ رَزَقَکَ اللہُ وَلَدًاسَوِیًّا.اورانہی معنوں میں یہ فقرہ بطور دعا کے کہاجاتاہے.کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بے عیب لڑکا عطا فرماوے(اقرب) نَفَخْتُ.نفخت نَفَخَ سے متکلم کاصیغہ ہے.اور نفخ(یَنْفُخُ نَفْخًا و نَفِیْخًا)بِفَمِہِ کے معنے ہیں.اَخْرجَ مِنْہُ الرِّیْحَ یعنے منہ سے ہوانکالی.وَ نَفَخَ فِی النَّارِ و نَفَخَھَا آگ میں پھونک ماری یعنی لفظ نفخ لازم اورمتعدی دونوں طرح استعمال ہوتاہے.نَفَخَ شِدْ قَیْہِ تَکَبَّرَ.تکبرکیا(ہمارے ہاں بھی اردو میں کہتے ہیں کہ منہ پھُلالیا)اورجب نَفَخَ الشَّیْطَانُ فِیْ اَنْفِہِ بولاجائے تواس کے یہ معنی ہوتے ہیں.تَطَاوَلَ اِلیٰ مَالَیْسَ لَہٗ کہ وہ ایسی امید لگابیٹھا جوپوری نہ ہوگی.یعنی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا جو اس کو نہیں مل سکتیں.(اقرب) الرُّوْحُ.مَابِہِ حَیَاۃُ الْاَنْفُس.وہ چیز جس کے ذریعہ نفوس زندہ رہتے ہیں.یعنی جس کو زندگی کہتے ہیں.الوحی الہام.جِبْرِیْل،جبرائیل.اَلنَّفْخُ پھونک.أَمْرُالنُّبُّوَّۃِ، امرنبوت.وَحُکْمُ اللہِ واَمْرہُ.خدا تعالیٰ کا فیصلہ اوراس کاحکم.تُطْلَقُ الْاَرْوَاحُ عَلَی مَایُقَابِلُ الْاَجْسَادَ جسم کے مقابل چیز کوبھی روح کہتے ہیں.(جو انسان میں جسم کے علاوہ موجود ہے )وَعِنْدَ اَصْحابِ الْکِیْمِیَا عَلی الْمَیَاہِ الْمُقَطَّرَۃِ مِنَ الْاَدْوِیۃِ.کیمیا والوں
Page 305
کے نزدیک دوائیوںکے عرق کوبھی روح کہتے ہیں.(لیکن یہ فن کی ناواقفی کی وجہ سے لکھا ہے کیمسٹری والے عرق کو روح نہیں کہتے.بلکہ یاتو تیل والی ادویہ کاوہ حصہ جو عرق پر آجاتاہے اسے روح کہتے ہیں جیسے روح گلا ب یا پھر عرق کو باربار کشید کرکے اس کی تیز خوشبوکو عرق سے الگ کرلینے پر اسے روح کہتے ہیں جیسے روح کیوڑہ) (اقرب)جبرائیل کو جو صاحب اقرب الموارد نے روح لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جبرائیل کو روح کہاگیاہے اس لئے انہوں نے روح کے معنے جبرائیل قراردے دیئے.جبرائیل کو روح کے نام سے پکارے جانے کی وجہ حالانکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بعض دفعہ مسبب کانام سبب کو دے دیاجاتاہے اوراسی لحاظ سے جبرائیل کو روح کہا گیا ہے.کیونکہ وہ روح یعنی کلام الٰہی کو لاتاہے.غر ض روح کے معنے جبریل نہیں بلکہ استعارۃً وحی لانے والے فرشتے کو کہتے ہیں.اصل میں روح وہ چیز ہے جس کے ذریعہ کسی کو حیا ت ممتاز ملے.پس وہ روح جو حیوان کو باقی چیزوں سے ممتاز کررہی ہے.اوروہ روح جس کے ساتھ انسان باقی حیوانوں سے ممتازہوتاہے ان دونوں پر لفظ روح کااطلاق ہوتاہے.یاوہ روح جوانسان کو باخدابنادیتی ہے پس کلام الٰہی بھی ایک روح ہے جو انسان کو نئی زندگی بخشتاہے.سٰجِدِیْنَ.السُّجُوْدُ.التَّذَلُّلُ.سجود کے معنی تذلل اورماتحتی کے ہیں.(مفردات) وَقَوْلُہٗ اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ قِیْلَ اُمِرُوْا بِالتَّذَلُّلِ لَہُ وَ الْقِیَامِ بِمَصَالِحِہٖ وَ مَصَالحِ اَوْلَادِہٖ.آیت اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ میںفرشتوںکو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدم کے ماتحت چلیں.اوراس کی مدد کریں اوراس کی اولاد کے لئے ممدّو معاون بنیں.وَقَوْلُہُ اُدْخُلُوْا الْبَابَ سُجَّدًااَیْ مُتَذَلِّلِیْنَ مُنْقَادِیْنَ.اورقرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ تم اس دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوجائو.اس کے معنے بھی یہی ہیں کہ تم فرمانبرداری کرتے ہوئے جائو.(مفردات) تفسیر.اس آیت میں ابتداء نسل انسان میں مکمل وجود کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے اس آیت میں ابتدائے نسل انسانی میں جو مکمل وجود پیداہواتھا.اس کو مثال کے طورپر پیش کیاہے کہ دیکھو! اسے بھی الہام ہوا.اوراللہ تعالیٰ نے اس کے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے فرشتوںکو لگادیا.پس یہ سلسلہ الہام اوراس کی حفاظت کا ابتداء عالم سے چل رہاہے.فرشتوں کو آدم ؑ کی فرمانبرداری کے حکم سے مراد سب مخلوق کی فرمانبرداری ہے اس آیت میں ملائکہ کو سجدہ یعنی آدم کی فرمانبرداری کاجو حکم دیا گیاہے.اس سے مراد سب مخلوق ہے کیونکہ تمام اسباب کی علّت اولیٰ ملائکہ ہی ہیں.ان کے حکم میں سب کو حکم مل گیا.اس حکم کایہ بھی مطلب ہے کہ اس دنیا میں آد م کو قدرت دی گئی ہے.
Page 306
اورسب مخلوق اس کے تابع کی گئی ہے.پس فرشتوں کو جو علّتِ اولیٰ ہیں.چاہیے کہ انسان جو کام کرے اس کے مطابق نتائج نکالتے جائیں.گویاقانون قدرت کے ماتحت ہرانسانی فعل کاخواہ وہ براہی ہو.نتیجہ نکالنے کافرشتوںکو حکم دیاگیاہے اور اس حصہ میں سب انسانوں کے انہیں تابع کیا گیا ہے یہ تو عام قانون ہے.لیکن جب انبیاء کے زمانہ میں تقدیر خاص جاری ہوتی ہے.توفرشتوں کایہ بھی فرض ہوتاہے کہ اس زمانہ کے آدم یعنی نبی وقت کی تائید کریں.اوراس کے دشمنوں کو ناکام بنائیں.فَسَجَدَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَۙ۰۰۳۱ جس پر سب کے سب فرشتوں نے(اس کی ) کامل فرمانبرداری اختیارکرلی.اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ١ؕ اَبٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ۰۰۳۲ سوائے ابلیس کے (کہ )اس نے (اس کی)کامل فرمانبرداری اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکارکردیا.حلّ لُغَات.اِبْلِیْسَ.ابلیس اَبْلَسَ مِنْ رَحمۃِ اللہِ کے معنے ہیں.یَئِسَ.ناامید ہوگیا.اوراَبْلَسَ فِی أَمْرِہِ کے معنی ہیں.تَحَیَّرَ.حیران ہوگیا.وَقِیْلَ اِبْلِیْسُ مِنْ اَبْلَسَ بِمَعْنَی یَئِسَ وَتَحَیَّرَ.یعنی اَبْلَسَ کے معنی ناامیداورحیران ہونے کے ہیں.اور اِبلیس اسی سے بناہے.یعنی ناامید اورحیران.اس نام سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہوگیا ہے.اورحیران رہ گیا ہے.جَمَعُہُ اَبَالِیْسُ وَ اَبَالِسَۃٌ.اس کی جمع اَبَالِیْسٌ اوراَبَالِسَۃٌ آتی ہے.(اقرب) تفسیر.اگر ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم تھا تو ابلیس سے کیوں باز پرس کی گئی یہاں سوال ہوتاہے کہ فرمانبرداری کاحکم اگرصرف فرشتوںکو ہی تھا توابلیس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کیوں باز پرس کی گئی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی بڑے افسر کو حکم ملاکرتاہے توا س کاماتحت بھی اس میں شامل ہوتاہے یہاں پر فرشتوں کو طبعی نتائج نکالنے کاحکم دیاگیا ہے یاآدم کے مشن کوکامیاب کرنے کا.اس لئے جو ان سے ادنیٰ مخلوق ہے وہ خود بخود اس حکم میں آجاتی ہے.جیسے بادشاہ ایک جرنیل کو حکم دیتاہے کہ فلاں جگہ جائو.توسپاہی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں.سپاہی یہ کہہ کر انکار نہیں کرسکتے کہ ہمیں حکم نہیں دیاگیا.فرشتوں کے حکم میں ابلیس کا حکم بھی شامل ہے پھر دوسری جگہ صاف فرما دیا ہے کہ مَامَنَعَکَ اَلَّا تَسْجُدَ
Page 307
اِذْ اَمَرْتُکَ(الاعراف:۱۳)تجھے باوجود میرے حکم کے آدم کو سجدہ کرنے سے کس بات نے روکاہے.اس آیت سے ظاہر ہے کہ فرشتوں کے حکم میں ابلیس کا حکم بھی شامل تھا.کیونکہ وہ بھی دوسری مخلوق کی طرح فرشتوں کے تابع ہے.آدم ا و رابلیس کے واقعہ کااصل مقام توسورئہ بقرہ ہے اسے دیکھناچاہیے.مگر میں مختصراً ایک بات یہاں بھی بیان کردیتاہوں اوروہ یہ ہے کہ یہ گفتگو جواس جگہ بیا ن کی گئی ہے ضروری نہیں کہ اسی طرح ہوئی ہو.آدم اور ابلیس کے واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے مکالمہ کا رنگ دیا گیا ہے مذہبی محاورہ میں خصوصاً اورعربی زبان میں عموماً یہ طریق استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی واقعہ کی حقیقت کو ظاہرکرنے کے لئے اسے مکالمہ کارنگ دے دیاجاتاہے.حالانکہ مکالمہ فی الحقیقت کو ئی نہیں ہواہوتا.قال کے استعمال کی وسعت چنانچہ عربی زبان میں قال کالفظ عام طورپر اس طرح ا ستعمال ہوتاہے مثلاً عرب کہتے ہیں.اِمْتَلَأَ الْحَوْضُ فَقَالَ قَطْنِیْ کہ جب حوض پانی سے بھر گیا.تواس نے کہا.کہ بس بس اب زیادہ پانی نہ ڈالو.اس کا یہ مطلب نہیںکہ حو ض زبان سے بولا.بلکہ یہ کہ حوض نے زبانِ حال سے بتایاکہ میں بھر گیاہوں(لسان العرب).قال کے سواء اورالفاظ بھی عربی میں استعمال ہوتے ہیں جن میں بظاہر ایک ارادی فعل کااشارہ ہوتاہے.مگرمراد صرف صور ت حال کا بیان کرنا ہوتاہے.مثلاً سورئہ کہف میں آتاہے.کہ حضرت موسیٰ اوران کے ساتھی ایک گائوں میں گئے.فَوَجَدَ افِیْھَا جِدَارًا یُّریْدُ اَنْ یَّنْقَضَّ(الکہف :۷۸) انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے کاارادہ کررہی تھی.اب یہ ا مر ظاہر ہے کہ دیوار میں دماغ نہیں کہ وہ ارادہ کرے.اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ دیوار کی حالت بتاتی تھی کہ وہ گرجائے.امام ابو منصورثعالبی جولغت عر ب کے امام ہیں.اپنی کتاب فقہ اللغۃ میں لکھتے ہیں کہ ابوفراس مشہور ادیب دل سے اسلام کا منکر تھا.اوراس کامشغلہ یہی تھا کہ قرآن کریم پر اعتراض کرتا رہے.ایک دفعہ ابوالعباس احمد بن حسین (جوخاندان عباسیہ کا ایک وزیر تھا )کے دربار میں ہم بیٹھے تھے اوروزیر کی آمد کاانتظار کررہے تھے.اسی دوران میں ابوفراس نے مجھ سے مخاطب ہوکرکہا کہ کیاکسی عرب نے کسی عقل نہ رکھنے والی چیزکے بارہ میں کبھی کہا ہے کہ اس نے ارادہ کیا.میں نے کہا عرب بعض دفعہ غیر ذی روح کے متعلق کہتے ہیں.اس نے یوں کہا جیسے مثال ہے.اِمْتَلَأَ الحوضُ فقال قَطْنِی.حالانکہ حوض توبولتا ہی نہیں اس نے کہا.میں قول کا ذکر نہیں کرتا.وہ تو بیشک درست ہے.مگریہ بتائو عقل نہ رکھنے والی اشیاء کی نسبت کبھی اراد ہ کالفظ آتا ہے.اس کی غرض یہ تھی کہ آیت یُرِیْدُ اَنْ یَنْقَضَّ َّ غلط ثابت ہو.اللہ تعالیٰ نے اس وقت میری مدد کی اورعرب کے شاعر الرّاعی کا شعر میرے ذہن میں آگیا جو میں نےاس کے سامنے پڑھا.اوروہ شعر یہ ہے.
Page 308
فِیْ مَھْمَہٍ فُلِقَتْ بِہِ ھَامَاتُھَا فَلْقَ الْفُئُوْسِ اِذَا اَرَدْنَ نُصُوْلًا یعنے ایک جنگل میں جہاں اس قوم کی کھوپڑیا ںتوڑ ی گئیں جس طرح کلہاڑا جب چلنے کاارادہ کرتاہے.تو(لکڑیوں کو)کاٹتاجاتاہے.میں نے کہا.اس جگہ کلہاڑے کی طرف چلنے کے ارادہ کو منسوب کیا گیاہے.کیا اس میں اراد ہ ہوتاہے.یہ شعر پڑھنا تھاکہ ابی فراس کے منہ کو تالے لگ گئے اورخدا تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا.اسی طرح وہ ابو محمد یزیدی کا واقعہ لکھتے ہیں.کہ میں اورمشہور نحوی کسائی عباس بن حسن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کا ایک نوکر آیا اورکہنے لگا.کہ حضور فلاں شخص کے پاس سے آیا ہوں.ھُوَیُرِیْدُ اَنْ یَمُوْتَ.وہ مر نے کااراد ہ کررہاہے اس پر ہم سب ہنس پڑے.عباس بن حسن نے کہا کس بات پر ہنستے ہو.ہم نے کہا کبھی کو ئی انسان اپنی موت کا آپ بھی اراد ہ کیا کرتاہے.انہوں نے کہا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.فَوَجَدَ افِیْہَا جِدَارًا یُّرِیْدُ اَنْ یَّنْقَضَّ.اس پر ہم سب شرمندہ ہوئے اورسمجھ گئے کہ اس غلام کی بات درست تھی.کسی امر کے اندازہ سے ظاہر ہونے کے لئے بھی قول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے غرض کسی امر کااندازہ سے ظاہر ہونا بھی قول اور ارادہ کہلاتاہے.اورواقعہ آدم اورابلیس بھی اسی قسم کاہے.ان کی عملی حالتوں کو مکالمہ کی شکل میں پیش کیاہے.اورایسااس لئے کیاگیا ہے کہ یہ واقعہ پرانے زمانہ کا ہے اور پرانے زمانہ میں مجازوتشبیہ کو کثرت سے استعمال کیاجاتاتھا.اور تمثیل میں بات کرنا سمجھانے کےلئے زیادہ مؤثر سمجھاجاتاتھا.چنانچہ آدم کاواقعہ مختلف کتب سابقہ میں اسی رنگ میں بیان ہواہے.پس ان کو سمجھانے کے لئے قرآن کریم نے بھی عربی محاورہ کے مطابق اسی رنگ میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے تاکہ انہیں سمجھنے میںآسانی ہو.تمثیلی کلام پہلی کتب میں اس قدر استعمال ہواہے کہ صفات الہٰیہ کو بھی تمثیلی رنگ میں ہی بیان کیاجاتاتھا.مثلاً کہا جاتاتھا خدا تعالیٰ بڑاتیر انداز ہے.وہ تیز رتھ میں بیٹھ کر ہرجگہ جا پہنچتاہے.وہ لوگوں کوسزادے کر بڑاپچھتاتاہے.اس کے ہاتھ بھی ہیں اورپائوں بھی(زبور باب آیت ۱۴.باب ۱۸ آیت ۹،۱۰.باب ۱۶ آیت ۱۱.پیدائش باب ۹ آیت ۱۰،۱۱).یہ تمثیلات خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں.مگر حقیقت کااظہا ر ا ن سے مقصود نہ تھا بلکہ انسان چونکہ ابتدائی حالت میں تھا.ان مثالوں سے حقیقت کو اس کے قریب کیاجاتاتھا.قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس میں اس طریق کو بدلاگیاہے.اس میں بھی مجاز اوراستعارہ اور تمثیل ہے.لیکن کہیں کہیں صرف ایک ذوق پیداکرنے کے لئے.ورنہ اہم امور کوصاف اورواضح زبان میں بیان کیا جاتا ہے.اوراگر کوئی تمثیل ہے تو ا سکے مضمون کو دوسری جگہ صا ف عبارت میں بیا ن کر دیاجاتاہے.
Page 309
تالوگ دھوکہ نہ کھائیں.آدم کے واقعہ میں مکالمہ زبان حال میں بیان ہوا ہے نہ کہ فی الحقیقت غرض آد م کے واقعہ میں جو مکالمہ ہے و ہ زبان حال میں بیان ہواہے.نہ کہ فی الحقیقت کوئی گفتگو اللہ تعالیٰ اورابلیس میں ہوئی.تورات اور ہندو لٹریچر میں خیر و شر کی قوتوں کا ذکر مکالمہ کے رنگ تورات ا ورہندو لٹریچر میں بھی خیر اورشرّ کی قوتو ں کا ذکر مکالمہ کی صورت میں کیا گیا ہے.ہندوئوں میں ہریشچندر کا مشہور قصہ ہے.اس میں بھی مکالمہ کی صورت میں یہ مضمون بیان کیاگیاہے.تورات میں بھی خیر اورشرّ کی قوتوں کامقابلہ مکالمہ کی صورت میں ایوب کی کتاب میں کیاگیا ہے.چنانچہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربا ر میں فرشتے اورشیطان حاضرہوئے اورایو ب کی نیکی کا ذکر چل پڑا.شیطان نے کہا کہ ایوب اس لئے نیک ہے کہ اسے سب کچھ ملا ہواہے.اس پر اللہ تعالیٰ نے ایوب کی آزمائش کرنے کی اسے اجاز ت دی.وغیرہ وغیرہ (ایوب باب۱آیت ۶تا۱۲)یہی وجہ ہے.کہ تورات والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایما ن نہیں لائے.کیونکہ آپؐ کے کلام میں تمثیلیں کم تھیں.اورواضح عبارتوںمیں مضمون بیان ہوئے تھے.وہ غلطی سے اپنی کتب میں بیان شدہ مضامین کو حقیقت سمجھ رہے تھے.جب اسلام نے اللہ تعالیٰ کی صفات اورملائکہ کے وجو د اوروحی اورنبوت کو صاف اورواضح عبارت میں بیان کیا.تووہ حیران ہوگئے اورسمجھے کہ یہ باتیں تورات کے خلاف ہیں اور سچائی سے دور ہیں.قرآن مجیدنے باوجود تصویری زبان کے استعمال کر نے کے بہت سی غلط فہمیاں دور کر دی ہیں مگر یاد رکھناچاہیے کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے ا س موقعہ پر تصویری زبان کو استعمال کیاہے.پھر بھی اس نے بہت سی غلط فہمیاں جو پہلی کتب سے پیداہو تی تھیں مٹادی ہیں.اور جو دھوکہ تصویر ی زبان سے لگ سکتاتھا اس کاازالہ کردیاہے.مثلاً بائیبل میں تو یہ کہا گیاتھاکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اصلی جنت میں رکھا اوراصل جنت کی علامت یہ ہے.کہ اس میں گناہ کاصدورنہیں ہوسکتا(پیدائش باب ۲ آیت ۱۵).لیکن باوجود اس کے بائبل کہتی ہے آدم نے گناہ کیا(پیدائش باب ۳ آیت ۱۷).لیکن قرآن کریم نے گو آدم کے مقام کانام بعض جگہ جنت رکھا ہے.مگر دوسری جگہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْ الْاَرْضِ خَلِیْفَۃَ.(البقرۃ:۳۱) کہہ کر اس مجاز کی حقیقت بھی بیان کر دی ہے.اسی طرح اوربہت سے مسائل آدم کے متعلق جو قصہ آدم میں بیان ہوئے ہیں وہ دوسری آیات کے ذریعہ سے یاانہی آیات کے بعض حصوں سے حل کردیئے گئے ہیں.اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کو خیر اورشر کی طاقت دی گئی.تودونوں قسم کے محرکات اس کے لئے ضروری
Page 310
تھے اس لئے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ دونوں پیداکئے گئے.اللہ تعالیٰ نے انسا ن کوپیداکر کے ملائکہ کو حکم دیا.کہ جس قسم کے یہ کام کرے.اس کے نتائج پیدا ہوتے چلے جائیں.لیکن آدم اوران کے ساتھیوں کے علاوہ بھی دنیا میں مخلوق تھی.جو آدم کے نظام کے تابع نہ ہوئی تھی.ان کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی شیطان کا ظلّ ہونے کی وجہ سے شیطان اور ابلیس کے ناموں سے پکاراہے.اورجو کچھ آدم اوراس کے درمیان ایک لمبے عرصہ میں گذرااسے ایک مختصر مکالمہ کی صورت میں بیان کردیاہے.شیطان مجسم ہو کر لوگوں سے باتیں نہیں کرتا یاد رہے کہ وہ شیطان جو بطورمحرک بدی کے پیدا کیا گیاہے اورایک غیر مرئی وجودہے جس طرح ملائکہ ہیں وہ خود آکر لوگوںسے باتیں نہیں کیاکرتا.نہ مجسم ہو کر انسانوں کو تکلیف دیتاہے.جو لوگ شامت اعمال سے نیکی کا مقام کھوبیٹھتے ہیں وہ اس کے ظل ہوجاتے ہیں اورانہی کے کاموں کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے.محرکات بدی شیطان کہلاتے ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے محرکات بدی کے ہوتے ہیں.وہ بھی شیطان کہلاتے ہیں.جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.کہ میراشیطان مسلمان ہوچکاہے(مسند احمد جلد اول بروایت ابن عباس ص۲۵۷)اس لئے وہ مجھے ہمیشہ نیکی کاحکم دیتاہے.آنحضرت ؐ کے شیطان کے مسلمان ہونے کا مطلب اس ارشاد سے مراد آپ کی یہی ہے.کہ جو اسباب لوگوں کو بدی کی تحریک کرنے کاموجب ہوتے ہیں.وہ میر ے کامل تقویٰ کی وجہ سے میرے لئے نیکی میں ترقی کرنے کاموجب ہوجاتے ہیں.ورنہ یہ مراد نہیں.کہ ہرآدمی کے لئے الگ الگ شیطان ہوتاہے.اورآپ کاشیطان مسلمان ہوگیاتھااگرایساتھا توپھر آپ استعاذہ وغیرہ کیوں کرتے تھے؟وہ اصلی شیطان تو اسی پہلی حالت میں موجود تھا.مگر خیالات اورجذبات میں جو حالات اس کی نیابت کرتے ہیں وہ آپؐ کے لئے مسلمان ہوگئے تھے.مگرانسانوں میں سےجو اس کی نیابت کرتے تھے وہ اپنی شیطنت پر قائم تھے.اورمسلمان نہ ہوئے تھے جیسے ابو جہل وغیرہ.فَقَعُوْالَہٗ سٰجِدِیْنَ میں ہ کی ضمیر تمام انسانوں کی طرف جاتی ہے فَقَعُوْالَہٗ سٰجِدِیْنَ.لَہٗ میں ہٗ کی ضمیر تمام انسانوں کی طرف جاتی ہے کیونکہ نفخ روح ہر انسان میں ہوتی ہے اورملائکہ بھی ہرایک کی مدد کے لئے مقررکئے گئے ہیں.صرف مدارج کے لحاظ سے نفخ روح کی قسم مختلف انسانوں کے لئے بدل جاتی ہے.پس مجملاً یہ حکم سب انسانوں کے لئے ہےاورخصوصاً اورتفصیلاً انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں.چنانچہ اس کاثبوت کہ یہ حکم سب
Page 311
نسانوں کے لئے ہے یہ ہے.کہ سورہ جاثیہ ع۲میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.وَسَخَّرَلَکُمْ مَّافِیْ السَّمٰوٰتِ وَمَافِیْ الْاَرْضِ جَمِیْعًا.(جاثیہ:۱۴) کہ اے انسانو!تما م چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگادی ہیں.قرآن مجید سے پتہ چلتاہے کہ کہ ہرشے کےلئے ملائکہ سبب اول ہیں.پس جب فرمایا کہ تمام چیزیں انسانوں کے فائدہ کے لئے مسخرکردی گئی ہیں.تواس سے یہ نتیجہ نکلاکہ فرشتے تمام بنی نوع انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں.ہاں! بعض اشیاء انسان کی غلطی سے اس کے قبضہ سے نکل کر اس کو نقصان پہنچانے لگ جاتی ہیں.اوروہ گویا شیطان کی اظلال ہوتی ہیں اورفرشتوں کے حکم سے باہر ہوجاتی ہیں.اگر شیطان کوئی مرئی وجود تھا تو اب کیوں نظر نہیں آتا یہ خیال کہ اس غیر مرئی شیطان نے ظاہر ہو کر آدم کا مقابلہ کیا بالبداہت غلط ہے اورتجربہ کے خلاف ہے.کیونکہ قرآن کریم سے معلو م ہوتا کہ و ہ آدم اوراس کی بیو ی کے پاس آیا.اوران سے اس نے باتیں کیں (الاعراف :۲۱.۲۲).اب اگر یہ وہی شیطا ن تھا.جو محرّک بدی ہے.توجن آنکھوں سے اُسے آدم نے دیکھاتھا.اورجس زبان سے آدم نے اس سے باتیں کی تھیں.انہی آنکھوں اوراسی زبان سے اب آدم کی اولاد کیوںاسے نہیں دیکھتی.اورکیوں اس سے باتیں نہیںکرسکتی.اورکیوں و ہ اب بھی لوگوں کے پاس آکر انہیں ورغلاتا نہیں؟قرآن کریم سے ہرگز ثابت نہیں کہ آدم کاجسم اورقسم کاتھا.اوراس کی اولاد کااورقسم کا ہے.کہ یہ سمجھا جائے کہ آدم تواسے دیکھ سکتا تھا.اورباتیں کرسکتاتھا.مگر اس کی اولاد ایسا نہیں کرسکتی.اورجب ابناء آدم ویسی ہی طاقتیں رکھتے ہیں جس قسم کی آد م رکھتے تھے.اورشیطان بھی وہی ہے بدلانہیں.تویقیناً آج بھی ہزاروں آدمیوں کووہ نظر آناچاہیے تھا.اورہر اک نیک آدمی کو اسے ظاہری جسم کے ساتھ ملناچاہیے تھا.تاکہ آدم کی طرح اسے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے.مگر لاکھو ں چھو ڑ ہزاروں بھی آدمی نہیں ملتے جو اس امر کی گواہی دیں.بلکہ سینکڑوں بھی نہیں.بلکہ دسوں بھی نہیں بلکہ ایک بھی نہیں جویہ کہتا ہو کہ کشف یا خواب کے سوا اس نے شیطان سے مل کر باتیں کی ہوں.سوائے قصے اورکہانیوں کے جو بے ثبوت ہیں.لیکن وہ شیطان جس کامیں نے ذکر کیا ہے اسی طر ح ہرنبی کے راستہ میں مشکلات پیداکرتاہے.جس طرح اس نے آدم کے وقت میں کیاتھا.اوراسی طرح اباء اوراستکبار کرتاہے جس طرح آدم کے وقت میں اباء و استکبار کیاتھا.بلکہ ہر راستباز سے اس کا ویسا ہی سلوک ہوتاہے.
Page 312
قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ۰۰۳۳ (اس پر خدا تعالیٰ نے )فرمایا(کہ )ا ے ابلیس تجھے کیا ہواہے کہ تو(اس کی )کامل فرمانبرداری اختیارکرنے والوں قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ کے ساتھ نہیں ہوتا.اس نے کہا(کہ)میں ایسانہیں کہ ایک ایسے بشر کی کامل فرمانبرداری اختیارکروں جسے تونے حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ۰۰۳۴ آواز دینے والی مٹی سے یعنی ایسےسیاہ گارے سے جس کی ہیئت تبدیل ہوچکی تھی پیدا کیاہے.تفسیر.لَمْ اَکُنْ لِّاَ سْجُدَ بھی تمثیلی زبان میں کلام ہے مخالفین آدم کے سردار نے کہا کہ یہ توذلیل وجود ہے کہ اطاعت کو اچھاقراردیتاہے.یہ اوراس کے اتباع تو نقال ہیں اوردوسروں کے پیچھے چلنے میں فخر محسو س کرتے ہیں لیکن میری طبیعت میں تو نے آزادی اورحریّت رکھی ہے.میں اس کی بات کس طرح مان سکتاہوں یہ بھی تمثیلی زبان میں کلام ہے.مطلب یہ کہ آدم کے نظام کو اس کے بڑے دشمن اوراس کے اَتباع نے حریت ضمیر کے خلاف سمجھا.اوراپنی ہتک قرار دیا.اوراس کے ماننے سے انکار کیا.اوراپنے رویہ کو آدم کے طریق سے بہتر قرار دیا.اسی مضمون کو طینی اورناری طبیعت کے الفا ظ سے بیا ن کیاگیاہے.قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌۙ۰۰۳۵ فرمایا(اگرتیرایہ خیال ہے )تَوتُو اس (مقام)سے نکل جا.کیونکہ تو یقیناً دھتکاراہواہے.حل لغات.رَجِیْم کے لئے دیکھو سورئہ حجرآیت نمبر ۱۸.تفسیر.فَاخْرُجْ مِنْهَامیںمِنْهَا سے مراد جنت نہیں مِنْہَا سے مراد مفسرین جنت لیتے ہیں (تفسیر البغوی و القرطبی ، سورة الحجرزیر آیت ھذا) لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ جنت اس سے مراد ہے جو مرنے کے بعد ملنی ہے تووہ ایسا مقام ہے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہوسکتا.اورجو ا س میں داخل ہو.اس سے نکالانہیں جاتا.پھر شیطان کو کیونکراس میں داخل ہونے دیاگیا.اورآدم کو اس سے کیونکر نکالاگیا؟اوراگر وہ جنت مراد نہیں.
Page 313
بلکہ کوئی ارضی جنت مراد ہے.توپھر بھی یہ سوال ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے اسے وہاں سے نکال دیاتھا.تووہ پھرواپس آدم کو ورغلانے کے لئے وہاں کس طرح آسکا.مِنْهَاسے مراد رضا ءالٰہی کا مقام ہے پس میرے نزدیک نہ صرف اُخروی جنت بلکہ کوئی دنیوی مقام بھی جو جنت کہلا سکے یہاں مراد نہیں.بلکہ جنت سے مراد وہ رضائے الٰہی کا مقام ہے.جونبی کی بعثت سے پہلے لوگوں کوحاصل ہوتاہے.کیونکہ گووہ غلطی پر ہوتے ہیں.مگرچونکہ ان پر نبی کے ذریعہ سے حجت نہیں ہوئی ہوتی.خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ محروم نہیں ہوتے.مگرجب نبی مبعوث ہو جاتا ہے اوراس کاوہ انکار کردیتے ہیںتو پھر افضال الٰہی کی جنت سے وہ محروم ہوجاتے ہیں.اس کامزید ثبوت یہ ہے کہ سورئہ بقرہ اوربعض دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو دھوکہ دینے کے بعد ابلیس اور اس کی ذریت کو آدم اوراس کی ذریت کے ساتھ ہی جنت سے نکالاگیا.پس معلوم ہواکہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کا جنت سے نکالاجاناکچھ اورمعنے رکھتاہے.وَّ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ۰۰۳۶ اورجزا(وسزا)کے دن تک یقیناً تجھ پر (میری)لعنت رہے گی حلّ لُغَات.اللعنۃ اللَّعْنَۃُ کے لئے دیکھو سورئہ رعدآیت نمبر۲۶.یوم کے لئے دیکھو سورۃ یونس آیت نمبر۴.ایَّا مٌ: اَ یَّامٌ یَوْمٌ کی جمع ہے.اَلْیَوْمُ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلَی غُرُوْبِ الشَّمْسِ.دن کا وقت الوقت مطلقا.مطلق وقت جو بھی اور جتنا بھی ہو.(اقرب) الدِّیْنُ کے لئے دیکھو سورۃ یونس آیت نمبر ۲۳.الدِّیْنُ.اَلْجَزَاءُ وَالْمُکَافَاۃُ.بدلہ اَلطَّاعَۃُ اطاعت.اَلذُّلُّ.ذلت ماتحتی.اَلْحِسَابُ.محاسبہ.اَلْقَھْرُوَالْغَلَبَۃُ وَالْاِسْتِعْلَاءُ.کامل غلبہ.وَالسُّلْطَانُ وَالْمُلْکُ وَالْحُکْمُ بادشاہت اور حکومت.التَّدْبِیْرُ تدبیر.انتظام وَاِسْمٌ لِجَمِیْعِ مَایُعْبَدُبِہِ اللہِ.تمام وہ طریق جن سے کوئی قوم خدا تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے.اَلْمِلَّۃُ مذہب و کیش.یعنی شریعت.اَلْوَرَعُ.نیکی.اَلْقَضَاءُ فیصلہ (اقرب) اس لفظ کے بعض معانی جو یہاں چسپاں نہ
Page 314
ہوتے تھے چھوڑ دیئے گئے ہیں.تفسیر.لعنت سے مراد لعنت کے معنی دوری کے ہوتے ہیں.جولوگ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے مخالفوں کے سردار ہوتے ہیں.ان کے نام کو مٹادیاجاتاہے.اورانبیاء کے ذکر کواجمالاً یاتفصیلاً قائم رکھاجاتاہے اور چونکہ نبوت ایک زنجیر ہے ہراگلانبی اوراس کی جماعت پہلے نبی اوراس کی جماعت کے ساتھ ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں.اس لئے ہمیشہ ہی انبیاء کے مخالفین کا ذکربُرے طورپر ہوتارہتاہے اورگونام لے کران پرلعنت نہ بھیجیں.مگردل ان کے افعال سے اظہارنفرت کرتے رہتے ہیں.اور چونکہ نبوت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا.اس لئے فرمایاکہ یوم الدین تک تم پر لعنت ہوگی.آیت اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ میں عذاب الٰہی کا ذکر نہیں ورنہ عذاب الٰہی کااس آیت میں ذکر نہیں.کیونکہ وہ توپوری شدت سے یوم الدین کے بعد شروع ہوگا.قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْۤ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ۰۰۳۷ اس نے کہا (کہ)اے میرے رب (پھر)تومجھے ان کے (دوبارہ)اُٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے حلّ لُغَات.اَنْظِرْنِیْ.اَنْظِرْنِیْ اَنْظَرَ سے ہے اوراَنْظَرَہُ الدَّ یْنَ کے معنے ہیں.اَخَّرَہَ.قرضدار کو قرضہ اداکرنے میں مہلت دی(اقرب) پس انْظِرْنِیْ کے معنے ہوں گے مجھے مہلت دیجئے.یُبْعَثُوْن.یُبْعَثُوْنَ بَعَثَ سے جمع مذکر غائب مجہول کاصیغہ ہے.اوربَعَثَہٗ(یَبْعَثُ بَعْثًا)کے معنے ہیں اَرْسَلَہٗ اس کو بھیجا.بَعَثَہُ بَعْثًا اَثَارہٗ وَھَیَّجَہٗ.اس کو اُٹھایااورجوش دلایا.بَعَثَ اللہُ الْمَوْتٰی.اَحْیَاھُمْ اللہ نے مردوں کو زندہ کیا.بَعَثَہٗ عَلَی الشَّیْءِ حَمَلَہٗ عَلٰی فِعْلِہِ.اس کو کسی کام کے کرنے پر اُکسایا.اَلْبَعْثُ.النَّشْرُ اُٹھانا.(اقرب) تفسیر.آدم میں نفخ روح سے مراد نزول الہام ہے جیسا کہ میں بتاچکاہوں ان آیات میں آدم اور دوسرے انبیاء کا ذکر خصوصاً اورابناء آدم کا عموماً ہے.اورآدم اور دوسرے انبیاء کے نفخ روح سے مراد نزول الہام ہے.اوربنوآدم کے نفخ روح سے مراد نفس ناطقہ کی تکمیل ہے.پس اس آیت میں جو یَوْمٌ یُبْعَثُوْنَ آیا ہے اس کے معنے بھی دونوں گروہوں کو مدنظر رکھ کر مختلف ہیں.بنوآدم کو مدنظر رکھ کر تو اس کے معنے یہ ہیں کہ جب تک ان کی
Page 315
بعثت روحانی نہ ہو.اس وقت تک مجھے مہلت دے.یعنے جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں شامل ہوکر شیطانی حملوں سے محفوظ نہ ہوجائے اس وقت تک شیطان اوراس کی ذریت کو ان کے ورغلانے کاموقعہ ملتارہے یہ کلام بھی زبانِ حال کی قبیل سے ہے.ورنہ یہ نہیں کہ شیطان نےیا اس کے اظلال نے واقع میں اللہ تعالیٰ سے لفظوںمیں اس طر ح کی مہلت طلب کی ہو.یوم بعث سے مراد روحانی بعث ہے اس امر کاثبوت کہ یوم بعث سے مراد روحانی بعث ہے نہ کہ حشر اجساد یہ ہے کہ اس جگہ موت تک نہیں فرمایا.بلکہ یوم بعث تک فرمایا ہے اوریہ ظاہر ہے کہ حقیقی یوم البعث تک موقع ملنے کے کوئی معنے ہی نہیں.کیونکہ مرنے کے بعد توعالم امتحان ختم ہو جاتا ہے.یہ توکسی مذہب کابھی عقیدہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی شیطان اورملائکہ لوگوں کو نیکی کی طرف لاتے یابدی کی تحریک کرتے ہیں.پس اگر یوم بعث سے یہاں حشر اجساد مراد لیاجائے تویہ آیت قرآنی تعلیم اورعقل سلیم کے مخالف ہوجاتی ہے.پس ہر عقلمند یہ ماننے پر مجبورہوگا کہ یہاں یوم بعث سے مراد روحانی بعث ہے اورمطلب یہ ہے کہ اسی وقت تک شیطان یا شیطانی لوگ کسی کو گمراہی کاسبق دے سکتے ہیں جب تک اس کا روحانی بعث نہ ہو یادوسرے لفظوں میں نفس مطمئنہ نہ ملاہو.روحانی بعث کے بعد شیطان مایوس ہو جاتا ہے جب نفس مطمئنہ مل جائے تو پھر شیطان اوراس کی ذریت اس بندے سے مایوس ہوجاتی ہے اورورغلانے کے طریقہ کو چھوڑ کر اسے جسمانی دکھ دینا شروع کردیتی ہے.یوم بعث سے مراد انبیاء کی کامیابی کا زمانہ دوسرے معنوں کے روسے یعنے آدم اوران کے حقیقی جانشین یعنے انبیاء کو مدنظر رکھتے ہوئے ا س آیت کے یہ معنے ہوںگے کہ شیطان اوراس کے اَتباع کو اس وقت تک ان کے کاموں پر نکتہ چینی کاموقع ملتاہے اوران کے کاموں میں روک پیداکرنے کی طاقت ہوتی ہے جب تک ان کا یوم بعث نہیں آتا.یعنی ان کی کامیابی کے لئے جو زمانہ مقدرہے وہ نہیں آجاتا.کامیابی کے زمانہ کے آنے تک شیطانی لوگ خوب ان پر حملے کرتے ہیں اورانہیں دکھ دیتے ہیں اور ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگاتے ہیں یعنے استراق سمع اورمَنْ خَطِفَ الْخَطْفَۃ کی بتائی ہوئی ڈھیل کے ماتحت ان کی تعلیم پر اعتراض کرتے اورجھوٹ بولتے ہیں.لیکن جب ان کایوم بعث آتاہے یعنی انہیں غلبہ اوراقتدار ملنا شروع ہو جاتا ہے توپھر شیطان جھاگ کی طر ح بیٹھ جاتے ہیں.آدم کے زمانہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ایسا ہی ہوتاچلاآیاہے.اور اللہ تعالیٰ کی حکمت شیاطین کو خوب شور مچانے اور طرح طرح کے مکر اورحیلے کرنے کی مہلت دیتی رہی ہے لیکن جب بھی یوم بعث آیا اورخدا تعالیٰ کی آواز نے اپنے نبیوں اوران کی جماعت کو آواز دی.کہ اب تمہاراامتحان ختم ہوااب
Page 316
اُٹھو اوردنیا پر چھا جائو.اس وقت ان کے مخالف زبد یعنے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے.بلکہ ان میں سے بہت ایمان لاکر ان کے حلقہ بگوش ہوگئے ان معنوں کے روسے بھی شیطان کامکالمہ مہلت کے متعلق ایک تصویری نقشہ ہے اوراس کے یہ معنے نہیں کہ نبیوں کے زمانے میں شیطان مہلت مانگتے ہیں اوران کوخدا تعالیٰ مہلت دیتا ہے.بلکہ یہ معنے ہیں کہ شیطان د ل سے خواہش کرتے ہیں کہ نبیوں پر حملہ کریں اورانہیں کچل دیں اور اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کوپوراہونے دیتاہے.مگریہ مہلت یوم بعث تک ملتی ہے.جب یوم بعث آتاہے تومہلت ختم ہوجاتی ہے اور سب اوندھے منہ گرجاتے ہیں.اوراپنی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں.قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَۙ۰۰۳۸اِلٰى يَوْمِ فرمایاتومہلت پانے والوں میں سے ہے(ہی) الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۰۰۳۹ معین وقت (کے آنے)کے دن تک تفسیر.یعنی بے شک تم کو مہلت ملے گی.مگروقت ِ معلوم تک.یعنی اس وقت تک کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے نبیوں کی ترقی کو روکاہواہوگا.جب ان کی ترقی کا زمانہ آئے گاتویہ مہلت ختم ہوجائے گی اوراے شیطانو!(یعنی نبی کے بڑے دشمنو)خدا تعالیٰ کے قہر ی نشان تم کو بھسم کردیں گے.یہ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ وہی ہے.جس کی نسبت اس سورۃ کے شروع میں آچکا ہے وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ(الحجر:۵)یعنی ہربستی جس نے نبیوں کامقابلہ کیا اورہم نے اسے ہلاک کیا اسے پہلے ہی دن ہلاک نہیں بلکہ ہرنبی کے کام کے مطابق اس کی قوم کو ایک وقت تک مہلت دی.کسی کو تھوڑی کسی کولمبی.کسی کو اس نبی کی حین حیات میں تباہ کیا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورموسیٰ علیہ السلام سے ہوا.اور کسی دشمن قو م کو نبی کی وفات کے بعد ہلاک کیا.جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا.
Page 317
قَالَ رَبِّ بِمَاۤ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَ اس نے کہا (کہ) اے میرے رب چونکہ تونے مجھے گمراہی والا ٹھہرایاہے میں ضرور ہی ان کے لئے (تیری)ساری لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَۙ۰۰۴۰ زمین میں (گمراہی کو) خوبصورت کرکے دکھائوںگا اورضرورہی ان سب کو گمراہ کردوںگا.حلّ لُغَات.اَغْوَیْتَنِیْ.اَغْوَیْتَنِیْ اَغْوٰی سے مخاطب کاصیغہ ہے.اَغْوَاہُ کے معنے ہیں اَضَلَّہُ اُسے گمراہ قراردیا یاگمراہ کیا.وَغَوَیَ وَغَوِیَ الرَّجُلُ ضَلَّ گمراہ ہوگیا (اقرب) پس اَغْوَیْتَنِیْ کے معنے ہوں گے تونے مجھے گمراہ قرار دیا.تفسیر.یہ بھی زبانِ حال کاکلام ہے یعنی وہ لوگ جو ابتداء میں ایما ن نہیں لاتے بعد میں اس غصہ سے کہ ہمیں شروع میں ایمان لانے کاموقع نہیں ملا.انبیاء کی جماعتوں کو تباہ کرناچاہتے ہیں اورانہیں تکالیف دے کر مرتد کرنے کی کوشش کرتے ہیں.جیسے کہ دوسری جگہ فرماتا ہے.تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآىِٕهَا١ۚ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ١ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ١ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ (الاعراف:۱۰۲) یعنے اے محمدؐ ! یہ وہ بستیاں ہیں جن کاحال ہم نے تجھے سنایاہے.ان کے پاس ہمارے رسول دلائل لے کر آئے.مگر وہ ایمان لانے سے محروم رہے.صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے شروع میں ان کے دعویٰ کا انکار کردیاتھا.اللہ تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگادیتاہے.جو انبیاء کا انکار کردیتے ہیں.آئمۃ الکفر کے ایمان نہ لانے کی وجہ ا س آیت میں بتایا ہے ائمۃ الکفر اس وجہ سے ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں کہ شروع میں انکارکر بیٹھتے ہیں.پھر ایمان لانے میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں اورمخالفت میں بڑھ جاتے ہیں اوراپنا غصہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرکے نکالتے ہیں.قرآن مجید کا انبیاء کے دشمنوں کی کوششوں کی طرف اشارہ اوراسی مضمون کی طر ف اس سورۃ کے شروع میں بھی اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے.رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ (الحجر : ۳)یعنے بہت دفعہ کفار کے دل میں حسرت پیداہوتی ہے کہ کاش ہم شروع میں ایمان لے آتے.اورہماری عز ت قائم رہتی مگر چونکہ انکار کرکے عزت کےمقام کوکھوچکے ہوتے ہیں.باوجود اس حسرت کے ایمان لانے سے گریزکرتے ہیں.اورضد میں بڑھتے جاتے ہیں.
Page 318
لَاُغْوِيَنَّهُمْمیں وہی کوشش مراد ہے جو انبیاء کے دشمن کرتے چلے آئے ہیں اور یہ جو فرمایا لَاُغْوِیَنَّھُمْ میں ضرور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا.یہ وہی کوشش ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں حضرت شعیب کے ذکر میں آیا ہے کہ ان کے دشمنوں نے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّکَ یٰشُعَیْبُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَکَ مِنْ قَرْیَتِنَااَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا(الاعراف:۸۹) یعنی اے شعیب ہم تجھے بھی اورتیرے ساتھ ایمان لانے والوں کوبھی اپنی بستی سے نکال دیں گےیاتم کو واپس ہمارے دین میں آنا پڑے گا.اورسورئہ ابراہیم میں فرمایا.وَقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِرُسُلِہِمْ لَنُخْرِجَنَّکُمْ مِّنْ اَرْضِنَااَوْلَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا (ابراہیم :۱۴) گویا ہرایک رسول کے دشمن یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم کو ایمان نہیں ملا تومومنوں کوبھی گمراہ کرکے چھوڑیں گے اوریہی وہ حالت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تھی.جس کی نسبت فرماتا ہے وَیُرِیْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوْاالسَّبِیْلَ (النساء:۴۵)یعنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہود چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی مرتد کردیں.اسی طر ح کفار کی نسبت آتاہے وَلَایَزَالُوْنَ یُقَاتِلُوْنَکُمْ حَتّٰی یَرُدُّ وْکُمْ عَنْ دِیْنِکُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا(البقرۃ:۲۱۸)یعنے کفار کا اگر بس چلے تویہ اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے کہ تم کو مرتد کرلیں.یعنے یہ توتم کو اپنے جیسابنانے کے لئے پورازورلگائیں گے مگر ایک دن اللہ تعالیٰ ہی ان کے زورکو توڑ دے گا.اوریہ مغلوب ہوجائیں گے.لَاُغْوِیَنَّھُمْکے ماتحت احمدیوںکی مخالفت یہی نظارہ آج کل احمدیوں کو دیکھناپڑ رہاہے.سب دنیا انہیں مرتد کرناچاہتی ہے مگر جسے خدارکھے اسے کون چکھے.کفر بھی کیسااندھاہوتاہے.بجائے اپنے پر ناراض ہونے کے کہ دین الٰہی کو کیوں چھوڑا.کافر خدا تعالیٰ پر ناراض ہوتاہے کہ اس نے مجھے کیوں ایمان نہ بخشا.اس لئے میں اس کے مومن بندوں کو بھی مرتد کرکے چھوڑوں گا.العیاذ باللہ.اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ۰۰۴۱ سوائے ان میں سے تیرے برگزیدہ بندوں کے (جو میرے فریب میں نہیں آسکتے) قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ۰۰۴۲ فرمایا (کہ)یہ (حفاظت الٰہی)میری طرف (آنے کی ) سیدھی را ہ ہے.تفسیر.آیت هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ کے دو معنی پہلے کہاتھاکہ جو بند ے چنے ہوئے ہوتے
Page 319
ہیں.وہ شیطانی تصرف سے بچ جاتے ہیں.اب اس کی تشریح کی کہ مخلص بندے کس طرح بنتے ہیں.اوراس کاطریق یہ بتایا کہ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ یعنے اس راستہ کابتانا میرے ذمہ ہے.هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّسے مراد الہام سے راستہ بتانا ہے میں الہام سے انہیں اپناراستہ بتائوں گااور جب الہام سے میں انہیں اپناراستہ بتائوں گااوروہ سیدھے میری طرف آئیں گے توشیطان کی طرف جو خدا تعالیٰ سے دورپھینکا ہواہے وہ جاہی نہیں سکتے.ان معنوں کے روسے صِرَاطٌ عَلَيَّ کے معنے ہوتے ہیں.صَرَاطٌ بَیَانُہُ عَلیََّّ یہ وہ راستہ ہے جس کابیان کرنا میر اکام ہے.یعنے مخلص بندے وہ نہیں جو اپنی عقلوں سے خدا کارستہ دریافت کرنے کی کوشش کریں.جوعقل پر انحصار کرتاہے شیطان کے قبضہ میں جاتاہے.لیکن جسے میں خود راستہ بتائوں وہ کسی صورت میں شیطان کے اثر کے نیچے نہیں آسکتا.کیونکہ اس کامحافظ اورنگران میں ہوتاہوں.اوروہ سیدھا بغیر ادھر ادھر بھٹکنے کے میری طرف آجاتاہے.دوسرے معنے اس آیت کے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ جو مخلص ہو ں یعنے چنے ہو ئے ہوں وہ توفورًا ہی مجھ کو پالیتے ہیں اوران کی بعد کی زندگی میری تلاش میں نہیں گزرتی اوروہ اس راستہ پر نہیں چل رہے ہوتے جو میری طرف آتاہے کہ گمراہی کا خطرہ ہو.اورشیطان انہیں میرے تک پہنچنے سے پہلے ہی اُچک لے جب وہ میر ے الہام سے مجھ کو پالیتے ہیں توان کی بعد کی زندگی اس راستہ پر چلنے پر گزرتی ہے جو میرے اوپر سے گذرتا ہے یعنے میراوصال تو وہ پہلے ہی پالیتے ہیں ان کی بقیہ زندگی ایک کے بعد دوسر ی صفات الٰہی کو حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے.ایسے اشخاص کے متعلق شیطان کی کیا مجال کہ ان کے قریب بھی آسکے.اس میں یہ نکتہ بتایا کہ گمراہی کاخطرہ ا سے ہوتاہے جو ابھی تلاش میں ہو.جسے خدامل گیا اورجو خداکے ملنے کے بعد صرف زائد قرب کی تلاش میں لگاہواہوتاہے اسے گمراہ کرنا کسی شیطان کی طاقت میں نہیں.آنکھوں دیکھی بات اورتجربہ کردہ طریق کے بعد کوئی شخص منکر ہوہی کس طرح سکتاہے؟
Page 320
اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ جو میرے بندے ہیں ان پر تیراہرگزکو ئی تسلط نہیں ہوگا.سوائے ایسے افراد کے جو تیر ے مِنَ الْغٰوِيْنَ۰۰۴۳ پیچھے چلیں یعنی گمرا ہ ہو ں.حل لغات.سُلْطٰن سُلْطٰنٌکے معنی ہیں دلیل.قبضہ.طاقت.مزید تشریح کے لئے دیکھو سورئہ ابراہیم آیت نمبر ۱۱.تفسیر.اس آیت میں دوسرے محفوظ گروہ کا ذکرکیا ہے.جو نبوت کے مقام پر تونہیں ہوتا.یابراہ راست ایمان توحاصل نہیں کرتا.لیکن نبیوںکے طفیل یا دوسرے خدارسیدوںکے طفیل صداقت کو پالیتا ہے ان کے متعلق فرمایاکہ ان کو بھی اس قدر حفاظت حاصل ہوتی ہے کہ شیطان کو ان پر تسلط حاصل نہیں ہوتا.بیشک شیطان ان پرحملہ کرتا ہے لیکن اس کاحملہ بہت کمزورہوتاہے اوران کو اس کے مقابلہ کی طاقت ہو تی ہے.اس لئے وہ بھی بالعموم بچ جاتے ہیں.ہاں! ان میں سے بعض جوایمان کو پوری طرح حاصل نہیں کرتے اورا ن کے ایما ن کی بنیاد کامل یقین پر نہیں ہوتی بلکہ ابھی کمزوری ان میں باقی ہوتی ہے اوروہ کبھی کبھی شیطا ن کی پیروی کرلیتے ہیں.یعنی گناہ کے مرتکب ہوجاتے ہیں ان کے لئے خطر ہ ہوتاہے کہ کبھی شیطان کے حملہ کا شکارہوجائیں اور شیطان کو ان پر تسلط حاصل ہوجائے مگر یہ تسلط بھی ان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوتاہے اورگناہوں کے ارتکاب کے بعد ہوتاہے.ورنہ شروع میں وہ بھی حفاظت الٰہی میں ہوتے ہیں.اس میں اس طرف بھی اشار ہ ہے کہ انسانی فطرت پاک ہے اور وہی گمراہ ہوتاہے جو خود اس فطرت کو خراب کرکے شیطان کے پیچھے چل پڑے اسی کی طرف اشار ہ ہے اس آیت میں کہ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰھَا (الشمس:۱۱)وہی ہلاک ہو تاہے جو اپنے نفس کو خراب کردیتا ہے اورگناہ کی مٹی میں دفن کردیتاہے.
Page 321
وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ۫ۙ۰۰۴۴ اوریقیناً جہنم ان سب کے (لئے )وعدہ کی جگہ ہے.لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ١ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌؒ۰۰۴۵ اس کے سات دروازے ہیں (اوراس کے )ہردرواز ہ کے لئے ان میں سے ایک مقرر حصہ ہوگا.حل لغات.جَھَنَّمَ جَھَنَّمَکے لئے دیکھو سورئہ رعد آیت نمبر ۱۹.دَارُ الْعِقَابِ بَعْدَ الْمَوْتِ (اقرب) موعد مَوْعِدٌکے معنی ہیں وعدہ.اقرار.وعدے کی جگہ (اقرب) تفسیر.دوزخ کے نگرانوں کی تعداد انیس بیان کرنے کا مطلب قرآن کریم میں دوزخ کے نگرانوں کی تعد ادانیس بیان فرمائی ہے (المدثر:۳۱).اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے نو حواس ہیں(گوعام طورپر پانچ مشہو رہیں لیکن درحقیقت سردی گرمی اوروقت اوروزن کاانداز ہ کرنے والے حواس کو ملایاجائے تو نو حواس ہوتے ہیں)پس یہ تعداد ان حواس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہے.یعنی نو ظاہر ی حواس اورنو باطنی حواس اور ایک ان پر داروغہ.یہ کل انیس ہوئے.جب انسان اٹھارہ حواس اوران کی نگران قوت ارادی سے کام نہیں لیتا.تو وہ گمراہ ہوجاتا ہے.پس اس نسبت سے اس پردوزخ میں انیس پہر ہ دار مقرر کئے جائیں گے.یہ بتانے کے لئے کہ تونے انیس طاقتوں کو غلط استعمال کیا.دوزخ کے سات دروازے کہنےسے مراد اوریہ جوسات دروازے بتائے ہیں.ان سے مراد ضرور ی نہیں سات ہی دروازے ہوں.کیونکہ سات اور ستر کا ہندسہ عربوں میں تکمیل یاکثرت کے اظہارکے لئے بھی استعمال ہوتاہے(مفردات امام راغب زیر مادہ سبح).اس محاورہ کے رو سے دوز خ کے سات دروازے ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کے کثرت سے دروازے ہوں گے اور تمام گناہوں کاخیال رکھاجائے گا.جہنم کے مختلف دروازے مختلف رنگوں کے لحاظ سے ہیں اور لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ جو فرمایا تواس کے یہ معنے ہیں کہ جس قسم کے گنا ہ ہوں گے ویسے ہی دروازہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا.جنت کے متعلق بھی احادیث میں آتا ہے کہ مختلف نیکیوں کے الگ الگ دروازے ہوں گے اورہرشخص اپنی مناسب حال نیکی کے راستہ
Page 322
سے جنت میںداخل ہوگا(ترمذی ابواب المناقب باب مناقب ابو بکر صدیقؓ).آیت لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ سے سورۃ بقرۃ کی ایک آیت کا حل اس جگہ جُزْئٌ کالفظ استعمال کیا گیا ہے اوراس کے معنے انسانی جسم کے ٹکڑے کے نہیں بلکہ دوزخیوں کی جماعت کے مختلف گروہ مرا د ہیں.اس آیت سے سورئہ بقرہ کی اس آیت کا حل ہو جاتا ہے.جو حضر ت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ چار پرندے لے لے اورپھر فرمایا کہ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا (البقرۃ:۲۶۱) پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک جزو کو رکھ دے اس جگہ مفسرین نے غلطی سے یہ معنے کئے ہیں کہ ان کو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے (تفسیر بغوی زیر آیت رب ارنی کیف تحی الموتی).حالانکہ چار پرندوں کے اجزاء سے وہی مراد ہے جو اس جگہ مراد ہے یعنے ان میں سے ایک ایک پرندہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے.اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍؕ۰۰۴۶ متقی (لوگ )یقیناً باغوں اورچشموں (والے مقام )میں ہوں گے.حل لغات.الجنَّۃ الجنۃکے لئے دیکھو سورئہ رعد آیت نمبر ۲۴.تفسیر.متقیوں کے جنات اور عیون میں ہونے کا مطلب عَیْن کے معنے چشمہ کے ہیں اورعُیُوْن میں ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چشموں کے اند رپڑے ہو ں گے بلکہ جنّٰت اورعیون کے اکٹھے ذکر سے یہ بتایا ہے کہ متقی ایسی جنت میں ہو ں گے جو چشموں والی ہوگی.اس آیت میں بتایا ہے کہ جہاں شیاطین کو کفرکرنے کی وجہ سے جہنم نصیب ہوگی.ا س دنیا میں جلن حسر ت اورپھر عذاب کی صورت میں اورآخر ت میں عذاب النا ر کی صورت میں وہاں مومن خدا تعالیٰ کے سایہ کے نیچے ہو ںگے اورعلوم کے چشمے ان کے دلوں سے پھوٹ رہے ہوں گے جن کی وجہ سے فضل کاسایہ اور بڑھے گا.جس طرح درخت کو پانی ملتا رہے تووہ بڑھتا رہتاہے اورآخرت میں وہ جنَّات و عیون نصیب ہوں گے جن کاوعدہ قرآن کی متعدد آیات میں دیاگیاہے.
Page 323
اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ۰۰۴۷ (انہیں کہا جائے گا کہ)تم سلامتی کے ساتھ بے خوف (وخطر)ان میں داخل ہوجائو.حل لغا ت.بِسَلٰمٍ بِسَلٰمٍکے لئے دیکھو سورئہ یونس آیت نمبر ۱۱و۲۶.سلام.سَلَامٌ سلام کے کئی معنی ہیں.اِسْمٌ مِنَ التَّسْلِیْم.باب تفعیل سے اسم مصدر ہے اور اس کے معنی سلامتی دینے کے ہیں.انقیاد یعنی فرمانبرداری.سلام خدا کا نام بھی ہے.کیونکہ وہ تمام عیبوں اور نقصوں سے پاک ہے.(اقرب) تفسیر.دارالسلام جنت کو بھی کہتے ہیں.اُدْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍملائکہ کا قول معلوم ہوتا ہے یہ ملائکہ کاقوم معلوم ہوتاہے یعنی ملائکہ ان سے اس دنیا میں بھی کہتے ہیں اوراگلے جہان میں بھی کہیں گے کہ سلامتی اورامن سے جنت میں داخل ہوجائو.چونکہ یہ لوگ ملائکہ کی نیکی کی تحریکات کو قبول کرتے ہیں اس لئے ملائکہ کو ان سے محبت اورانس ہو جاتا ہے.اور وہ الٰہی فیصلوں کو جو مومنوں کے بارہ میں ہوتے ہیں.دوڑ دوڑ کر انہیں سناتے ہیں اوریہ جو فرمایاسلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہوجائو اس میں دو سلامتیوں کو ذکر ہے.اندرونی اوربیرونی.کشمکش اوراضطراب سے نجا ت کی طرف سلام سے اشارہ کیاگیاہے اوربیرونی تکالیف اورعذابوں سے نجات کی طرف آمنین سے اشارہ کیا گیا ہے.سَلَام کے لفظ سے اللہ کے ایک وعدے کی طرف اشارہ نیز سلام کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کے ایک وعدہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان الفاظ میں ہے.سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَّبِّ رَّحِیْمٍ(یٓس:۵۹) یعنے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے خاص سلام مقدر ہے.اس کی ہم تم کو خبر دیتے ہیں یہ فرشتوں کاکہنا ان کےمومنوں سے شدید تعلق پر دلالت کر تاہے گویا وہ الٰہی فیصلوں کو ان تک جلد سے جلد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کاحکم نازل نہ ہو.انسان کو امن نصیب نہیں ہوتا.اوراس شیطانی قول کی طر ف بھی اشارہ ہے کہ ہم مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے.سوفرمایا باوجود ان کی کوششوں کے تم میرے برکتوں والے گھر میں آہی پہنچے.
Page 324
وَ نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰى سُرُرٍ اور ان کے سینوں میں جو کینہ (وغیرہ)بھی ہوگا اسے ہم نکال دیں گے (وہ)بھائی بھائی بن کر (جنت میں رہیں گے مُّتَقٰبِلِيْنَ۰۰۴۸ اور)تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے (بیٹھے )ہوں گے.حلّ لُغَات.غِلٌّ غِلٌّ غَلََّّ کا مصدر ہے اور غَلَّ صَدْرُہُ غِلًّا کے معنے ہیں.کَانَ ذَاغِشٍّ اَوْ حِقْدٍ وَضِغْنٍ.سینہ میں کینہ حقد اورغصہ بھر گیا.اورالْغِلُّ کے معنے ہیں الغِشُّ وَالْحِقْدُ کینہ اورحقد (اقرب) پس نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ ٍّ کے معنے ہوں گے کہ ہم ان کے دلوں سے کینہ وغیرہ نکال دیں گے.سُرُرٌ.سُرُرٌسَرِیْرٌ کی جمع ہے اورالسَّرِیْرُ کے معنے ہیں التَّخْتُ تخت.وَیَغْلِبُ عَلَی تَخْتِ الْمَلِکِ اوراکثر بادشاہ کے تخت پر بولاجاتا ہے یقَالُ’’ زَالَ عَنْ سَرِیْرِہٖ اَیْ ذَھَبَ عِزُّہُ وَنِعْمَتُہُ‘‘ اورجب زَالَ عَنْ سَرِیْرِہٖ کامحاورہ بولیں تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اس کی عزت جاتی رہی.اَلْمُلْکُ بادشاہت اَلنِّعْمَۃُ نعمت.خَفْضُ الْعَیْشِ.خوب مزے کی زندگی.(اقرب) تفسیر.دنیا میں جو مومن بھائی کا بغض دل سے نکال دے وہی جنتی بن سکتا ہے ایک اورجگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ جَنَّتٰنِ(الرحمٰن :۴۷) کہ مومن کو دوجنتیں ملتی ہیں ایک اسی دنیا میں اوردوسری اگلے جہان میں.اس جگہ پر جنت کی شرط یہ بتائی کہ وہاں دلوں میں غل نہ ہوگا.پس اس دنیا میں جو مومن بھائی کابغض دل سے نکال دے وہی جنتی بن سکتاہے.احمدیہ جماعت اور تمام مسلمانوں کو نصیحت اس سے ہماری جماعت اور تمام مسلمانوں کو فائدہ اٹھاناچاہیے کہ کسی کا کینہ دل میں نہ رکھیں.عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ کہہ کر بھی ان کی باہمی محبت کااظہار کیاہے کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تبھی ایک دوسرے کاچہرہ دیکھتے ہیں اورایک دوسرے کی طرف منہ کرکے بیٹھتے ہیں.عَلٰى سُرُرٍسے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر شخص ہی وہاں بادشاہ ہوگا سُرُرٌپر قرآن مجید نے بہت زوردیا ہےاور مختلف مواقع پر مختلف الفاظ میں یہ مضمون بیان ہواہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر شخص ہی وہاں بادشاہ ہو
Page 325
گا.دوسروں کی محکومی سے نجات مل جائے گی اورصرف خدا تعالیٰ کی بادشاہت ہو گی.جس کاحکم بوجھ نہیں ہوتا بلکہ اس کی اطاعت قوت وشان کو بڑھانے والی اورحقیقی آزادی دینے والی ہوتی ہے.قرآن مجید میں آتا ہے لَھُمْ فِیْھَا مَا یَشَاءُ وْنَ ( النحل:۳۲) جنت میں ان کی ہر ایک خواہش پوری کی جائے گی گویااپنے اپنے دائرہ میں ہر اک کاقانون نافذ ہوگا.اوریہی مفہو م بادشاہت کا ہے.لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّ مَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ۰۰۴۹ نہ انہیں ان میں کو ئی تکان ہوگی اورنہ انہیں ان سے کبھی نکالاجائے گا.حلّ لُغَات.نَصَبٌ نَصَبٌ نَصِبَ(یَنْصَبُ) کا مصدر ہے.اورنَصِبَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں اَعْیَا.تھک گیا (لازم)نَصِبَ فِی الْاَمَرِ.جَدَّ وَاجْتَہَدَ.کسی کام میں کوشش اورمحنت کی (اقرب)پس النَّصَبُ کے معنے ہوں گے تکان.تفسیر.لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌسے یہ بتایا ہے کہ جنت میں بھی انسان کام کریں گے فرمایا ان کو جنت میں نہ کسی قسم کی تکان پہنچے گی اورنہ وہ اس سے نکالے جائیں گے.اس میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں بھی انسان کام کر یں گے.لیکن فرق یہ ہوگا کہ وہاں فنا نہ ہو گی.کیونکہ تکان فنا کی علامت ہوتی ہے تکان کے معنی ہی یہ ہوتے ہیں کہ انسان کے جسم سے کچھ ذرات چربی یا اور کسی مفید جزو کے نکل گئے ہیں.اورتکان کام چھوڑنے اورآرام کرنے کے لئے طبیعت کا اعلام ہوتاہے یا غذاکھانے کے لئے.میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہاتھ کی ایک حرکت میں انسانی جسم کے کئی ملین سیل ضائع ہوجاتے ہیں.پس کچھ مدت کام کرنے کے بعد جب تکان محسوس ہوتی ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جسم سے کافی طاقت ضائع ہوچکی ہے اب اس نقصا ن کا ازالہ کرو.تھکان تحلیل جسم کا نتیجہ ہے جنت میں تحلیل جسم نہ ہوگی پس تکان فنا کی علامت ہے اوریہ کہہ کر کہ وہاں تکان نہ ہوگی یہ بتایا ہے کہ وہاں تحلیل جسم نہ ہوگی.اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ غذاجو بدل مایتحلل کے طورپرہوتی ہے وہاں ا س کا کام یہ نہ ہوگا کہ فنا شدہ کو پھر قائم کرے بلکہ مزید طاقت دینا کام ہوگا گویااس زندگی میں قدم پیچھے کسی طرح نہ ہٹے گا صرف آگے ہی بڑھناہوگا.
Page 326
چونکہ اس عارضی فنا کے نتیجہ میں جو تکان کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے انسان کو موت آتی ہے.کیونکہ آہستہ آہستہ جسم کی قوتیں ضائع ہوجاتی ہیں اورجنت میں اس قسم کے نقصان کی نفی فرمائی ہے.اس لئے فرمایا کہ وہ وہاں سے نکالے نہ جائیں گے یعنی اب ان کے لئے کوئی موت نہیں.جنت کی نعماء انسانی دماغ نہیں سمجھ سکتا یاد رہے کہ جنت ایک روحانی مقام ہے اورگوتمثیلی زبان میں اس نعماء کو دنیا کی نعما ء سے مشابہت دی گئی ہے.لیکن درحقیقت اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسانی دما غ انہیں سمجھ ہی نہیں سکتا.اس آیت میں درحقیقت اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں توانہیں شیطانوں سے جدوجہدکرنی پڑتی تھی.وہاں وہ اس جدوجہد سے بالکل بچ جائیں گے.اور ان کے دل ہرکوفت سے محفوظ ہوجائیں گے اورنہ عارضی طور پر شیطان ان کو نقصان پہنچاسکے گا نہ مستقل طورپر.جنت کام کرنے کی جگہ ہے نہ کہ عیش کا مقام اس آیت سے یہ بھی استدلال ہوتاہے کہ جنت سست الوجودوں کی سرائے نہیں.بلکہ اس میں رہنے والے بھی کام کریں گے کیونکہ اگر کام نہ کرنا ہوتاتوتکان کی نفی کی کیا ضرورت تھی ؟ پس جولوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ایک کھانے پینے اورعیش کرنے کا مقام ہے وہ غلطی کرتے ہیں.جنت توعبودیت کا اصل مقام ہے.جیسے فرمایا فَادْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ( الفجر:۳۰،۳۱) یعنے کامل عبودیت کا مقام جنت میں داخلہ کے وقت حاصل ہوگا اورعبد کام کیاکرتاہے نہ کہ سست بیٹھتا ہے.پس اصل کام کا مقام توجنت ہی ہے جہاں انسان کامل عبد ہوجائے گا.جنت کاسارا مزہ اس میں ہے کہ جذبات کی کشمکش سے آزاد ہو کر انسان اپنی عبادات میں لذت ہی لذت محسوس کرے گا اورجس کام میں لذت حاصل ہو اس میں تکان محسوس نہیں ہوتی.عام طورپر مسلمان جنت کا نقشہ پُؤرہائو س(مسکینوں کے رکھنے کی جگہ)کاسمجھتے ہیں.کہ کام کچھ نہ کریں گے کھانامفت ملتا رہے گااورکوئی وہاں سے باہر بھی نہ نکالے گا.لاحول ولا قوۃ الاباللہ العلی العظیم.نَبِّئْ عِبَادِيْۤ اَنِّيْۤ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُۙ۰۰۵۰ (اے پیغمبر)میرے بندوں کو آگاہ کردے کہ میں بہت ہی بخشنے والا(اور)بارباررحم کرنے والاہوں.تفسیر.غفور کے بعد صفت رحیم لانے کی وجہ اَنَاالْغَفُوْرُالرَّحِیْمُ.اس جگہ عِبَادِیْ کالفظ عام معنوں میں استعمال کیاگیا ہے اورنیک اوربد سب بندے اس میں شامل ہیں.فرمایا ہے کہ میرے بندے نیک
Page 327
ہوں یا بد ان سب کو اطلاع دے دو کہ میں غفور ہوں.اوررحیم ہوں یعنی گناہ گاروں کو تسلی دو.گھبرائیں نہیں.اوراس خیال سے مایوس نہ ہوں.کہ بہت گناہ ہوئے اب کیاہو سکتا ہے.میں غفورہوں ان کے سب گناہ بخش سکتا ہوں.اورمومنوں سے کہہ دو کہ وہ نیکی کرکے بس نہ کردیں.اوریہ خیال نہ کریں کہ جو کمال ہم نے حاصل کرناتھا کرلیا.کیونکہ میں رحیم ہوں میں بار بار رحم کرنے والاہوں.وہ جس قدر بھی نیکی میں ترقی کرتے جائیں گے میرارحم اوربڑھتاجائے گاپس انہیں نیکیوں میں ترقی کرتے رہناچاہیے.وَ اَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ۰۰۵۱ اور(یہ)کہ میراعذاب ہی (حقیقتاً) دردناک عذاب(ہوتا)ہے.حلّ لُغَات.اَلْعَذَابُ.العَذَابُ کُلُّ مَاشَقَّ عَلَی الْاِنْسَانِ وَمَنَعَہٗ عَنْ مُرادِہِ.عذاب کے معنی ہیں جو انسان پر شاق گذرے اورحصول مراد سے اسے روک دے وَفِی الْکُلِّیَّات کُلُّ عَذَابٍ فِی الْقُرْآنِ فَھُوَ التَّعْذِیْبِ اِلَّا وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَۃٌ فَاِنَّ الْمُرَادَ الضَّرْبُ.اورکلیات میں لکھا ہے کہ عذاب سے مراد قرآن مجید میں عذاب دیناہوتاہے سوائے آیت وَلْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا کے.وہاں سزامراد ہے.(اقرب) تفسیر.فرمایا میرے عذاب کے مقابلہ میں کسی دوسرے کاعذاب.عذاب کہلانے کامستحق ہی نہیں.کیونکہ اول تو وہ عارضی ہوتاہے دوسرے اس سے بچنے کاایک ذریعہ یعنے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے.لیکن جب عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے توپھر کوئی پناہ باقی نہیں رہتی.ا س صورت میں تو لَامَلْجَائَ وَلَامَنْجَأَ مِنْکَ اِلَّا اِلَیْکَ ہی کہنا پڑتا ہے.وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَۘ۰۰۵۲ اورانہیں ابراہیم کے مہمانوںکے متعلق (بھی )آگاہ کر.تفسیر.حضرت لوط ؑ کا ذکر حضرت ابراہیم ؑ کے ذکر سے شروع کیا جاتا ہے ا س جگہ دراصل حضرت لوط ؑ کا ذکر شروع کرنا تھا.مگر جیساکہ میں بتاچکاہوں ہمیشہ حضرت ابراہیم کے ذکر سے ہی حضرت لوط ؑ کا ذکر شروع کیا جاتا ہے.اتفاقی طور سے نہیں بلکہ یہ ذکر عمدًاکیا جاتا ہے.چنانچہ جہاں کہیں تفصیلی طور پر
Page 328
حضرت لوط ؑ کا واقعہ آیا ہے وہاں حضرت ابرہیم کے ذکر سے ہی ان کا ذکر شروع کیاگیاہے.اوراس سے یہ بتایاگیا ہے کہ حضرت لوط ؑ حضرت ابراہیم ؑ کے ماتحت رسول تھے.حضرت لوط اور ابراہیم ؑ کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اس واقعہ کو آدم علیہ السلام کے واقعہ کے بعد اس لئے بیان کیاگیاہے کہ اہل مکہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے سمجھتے تھے.اور حضرت لوط ان کے رشتہ دار تھے پس ایک طرف تویہ بتایاکہ الہام الٰہی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ؑپر بھی نازل ہواتھا.اور تم ان کے حالات سے واقف ہو.پھر آج الہام کے متعلق شبہات کیوں پیداکرتے ہوں؟دوسرے انہیں اپنے باپ دادوں کے واقعات سے یہ بتایا گیا کہ وحی الٰہی کا انکار انسان کو سزاکامستحق بنادیتاہے.اس طرزبیان سے ان لوگوں کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی ترتیب نہیں.اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا١ؕ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ جب وہ اس کے پاس آئے اورکہا (کہ ہم تمہارے لئے )سلامتی(کاپیغام لائے ہیں)اس نے کہا (کہ )ہم وَجِلُوْنَ۰۰۵۳ (تو)یقیناً تم سے ڈررہے ہیں.حلّ لُغَات.وَجِلُوْن.وجلون وَجِلَ(یَوْجَلُ وَجَلًا)کے معنی ہیں.خَافَ.ڈر گیا.وَفِیْ مُفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ اِستَشْعَرالْخَوْفَ اورمفردات میں وَجِلَ کے معنی یہ کئے گئے ہیں کہ خوف کو محسوس کیا.اس سے صفت مشبّہ الوَجِلُ ہے جس کے معنے ہیں اَلْخَائِفُ ڈرنے والا.(اقرب) وَجِلُوْن ا س کی جمع ہے.تفسیر.حضرت ابراہیمؑ کے مہمانوں کے چہروں پر رنج و غم کے آثار کی وجہ معلوم ہوتاہے ان کے چہروں پر رنج اورغم کے آثارتھے کیونکہ وہ ایک عذاب کی خبر لے کر آئے تھے.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذہانت سے ان کے قلب کی حالت کو تاڑ لیا.یایہ کہ جیسا سورئہ ہود میں ذکر آچکا ہے.حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لئے کھانالائے انہوں نے کھانے سے انکار کیا.اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ کیا کہ یہ لوگ کسی تکلیف دہ بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اورشائدسمجھا کہ جو یہ خبر لائے ہیں.وہ ان کے (یعنے حضر ت ابراہیم علیہ السلام کے )لئے بھی تکلیف دہ ہوگی اس وجہ سے انہوں نے کہاکہ آپ لوگوں کا کھانانہ کھانا تو دل میں ڈر
Page 329
پیداکرتاہے کہ آپ لوگوںکا سفرکوئی خیر کاسفر نہیں.اس سورۃ میں کھانالانے اوران کے انکار کرنے کے حصہ کو چھوڑ دیاگیاہے.مہمانوں کے کھانا نہ کھانے سے حضرت ابراہیم ؑ کو ڈر محسوس ہوا یہ بھی معنے ہوسکتے ہیں چونکہ انہوںنے کھانانہ کھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہواکہ شاید مہمانی میں کوتاہی ہوئی ہے اورفرمایا کہ میں تو آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے خفاہوگئے ہیں.قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ۰۰۵۴ انہوں نے کہا (کہ)توخوف نہ کر ہم تجھے یقینا ایک بہت علم (پانے)والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں.تفسیر.حضرت ابراہیم ؑ کو غلام علیم کی بشارت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فکر انہوں نے دیکھی تو ایک خبر جو وہ حضرت ابراہیم کے بارہ میں لائے تھے.انہیں سنائی اورکہا کہ ہمارے سفرکا تکلیف دہ حصہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ آپ کے لئے توہمیں ایک بشارت معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں اولادہوگی اور ایک بیٹاپیدا ہوگا جو بہت علم والا ہوگا.یہ امر قابل تعجب نہیں کہ حضرت لوطؑ اور حضرت ابراہیمؑ کی نسبت ان لوگوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو الہام ہواہو.کیونکہ کبھی مومن کے لئے دوسرے کو خبر دی جاتی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں.یَرٰہَاالْمُؤْمِنُ اَوْتُٰری لَہٗ (ترمذی ابواب الرؤیا،باب قولہ ولھم البشریٰ فی الحیوة الدنیا) مومن کبھی خودبشارت پاتا ہے کبھی اس کے لئے دوسرے کو الہاماً خبر بتادی جاتی ہے.حضرت ابراہیمؑ کے مہمان اس ملک کےتھے جہاں انہوں نے ہجرت کی تھی میرے نزدیک چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ان علاقوں میں مہاجر تھے اورعراق کے علاقہ سے ہجرت کر کے آئے تھے چنانچہ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اُورجو کسدی قوم کے علاقہ میں تھا باشندے تھے (پیدائش باب ۱۱آیت ۲۷و۲۸ نیز باب۱۲آیت ۴) اورجیسا کہ قرآن کریم میں بھی لکھاہے کہ جب حضرت ابراہیم کو ان کی قوم نے دکھ دیا توانہوں نے کہا اِنِّی مُہَاجِرٌ اِلیٰ رَبِّیْ (العنکبوت :۲۷)میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرجائوں گاچنانچہ وہ وہاں سے ہجرت کرکے کنعان کے ملک میں آبسے تھے.جیسا کہ سورئہ انبیاء میں ہے کہ وَنَجَّیْنَاہٗ وَ لُوْطًا اِلیٰ الْاَرْضِ الَّتِیْ بٰرَکْنَا فِیْہَا لِلْعَالَمِیْنَ(الانبیاء :۷۲) یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ترقی کرگئی اورآگ تک میں ان کو ڈالا گیا
Page 330
جسے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈاکردیا توہم نے ابراہیم علیہ السلام اورلوط کو اس ملک سے نجات دے کر اس زمین میں پہنچا دیا جو برکت والی ہے.اورقوموں کو اس جگہ برکت ملتی رہی ہے.یعنے کنعان کاعلاقہ جسے اب فلسطین کہتے ہیں اورجس میں یوروشلم وغیرہ یہود کے مقدس مقامات ہیں (نیز دیکھو پیدائش باب ۱۲آیت ۵)غرض حضرت لوط چونکہ اس علاقہ میں نئے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کہ حضرت لوط کواپناگائوں چھوڑنے پر تکلیف ہوگی.ان لوگوںکو جومعلوم ہوتا ہے اسی ملک کے تھے الہام کرکے روانہ کیاتا وہ آئندہ قیام کے متعلق انہیں مشورہ دیں اورتسلی دیں.حضرت لوط کی قوم کی تباہی کے ساتھ حضرت ابراہیم کو لڑکے کی بشارت دئیے جانے کی حکمت یہ جو فرمایا کہ آپ کو غلامٌ علیم کی بشارت دیتے ہیں.یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لئے خبردی.کیونکہ وہ بہت نرم دل تھے.فرماتا ہے اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ (التوبۃ:۱۱۴)یعنے حضرت ابراہیم دوسروں کے دکھ کو بہت محسوس کرتے تھے.پس اللہ تعالیٰ نے ان کے نازک دل کی تسلی کے لئے ان لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کوساتھ ہی لڑکے کی بشار ت دیتے جانا جو علیم ہوگا.تااس کے دل کوتسلی ہوکہ اگراللہ تعالیٰ ایک قوم کوتباہ کررہا ہے تو ایک اورنیک قوم کی بنیاد بھی رکھ رہا ہے چونکہ سچاعلم نبوت سے حاصل ہوتاہے اس لئے علیم میں حضر ت اسحاق کی نبوت کی بشارت بھی مراد ہوسکتی ہے.اِنَّا نُبَشِّرُكَ کے الفاظ اس قدرزوردار ہیں کہ ان سے معلوم ہوتاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت ملی تھی کہ چونکہ اس ہلاکت و تباہی کی خبر سے حضرت ابراہیم کو صدمہ ہوگا.اس لئے تم اس کے ساتھ ہی اس کو یہ بشارت بھی دینا.قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰۤى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ اس نے کہا (کہ)کیا تم نے مجھے (اب فی الواقع)بشارت دی ہے باوجوداس کے کہ مجھ پر بڑھاپاآچکا ہے پس تُبَشِّرُوْنَ۰۰۵۵ بتائو کہ کس بناپر تم مجھے (یہ) بشارت دیتے ہو.تفسیر.فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَمیں خبر کی بناءکے متعلق سوال ہے حضرت ابراہیم نے کہا میں تو اب بہت بوڑھا ہوچکاہوں پس یہ تمہاری خبرضرورالہامی ہے اگرایساہے تو مجھے بھی بتائو فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَکے اس جگہ یہ معنی نہیں کہ تم مجھے کس امر کی بشارت دیتے ہو.بلکہ یہ ہیں کہ تم کس حق کی بناء پر یہ بشارت دیتے ہو.تمہاری اس خبر
Page 331
کی بنیاد کیا ہے.قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ۰۰۵۶ انہوں نے کہا (کہ ) ہم نے تجھے سچی بشارت دی ہے پس توناامید مت ہو.حل لغات.قَنَطَ.قَنَطَ(یَقْنُطُ.قُنُوْطًا)کے معنے ہیں.یَئِسَ.ناامید ہوگیا.اس سے اسم فاعل قَانِطٌ آتاہے یعنی ناامید ہونے والا.(اقرب) تفسیر.انہوں نے کہا ہم نے بلاوجہ بشارت نہیں دی ہم انسان ہیں انسان ہونے کے لحاظ سے ہماراکوئی حق نہیں کہ کوئی بشارت دے سکیں مگریہ بشارت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اورہم اس کے دیئے ہوئے حق یااسی کے مناسب موقعہ ارشادکے ماتحت بشارت دیتے ہیں.پس تو ناامید نہ ہو.فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے مہمان بشر تھے نہ کہ فرشتے فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ بشر تھے.اگرفرشتے ہوتے توحضرت ابراہیم کو ان الفاظ میں خطاب نہ کرتے.کیونکہ فرشتے توحضرت ابراہیم کے مقام کو خوب جانتے تھے.ہاں بشرکے لئے ممکن ہے کہ وہ ناواقفیت کی وجہ سے ایساکہہ دے.قَالَ وَ مَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖۤ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ۰۰۵۷ اس نے کہا(کہ میں کیونکر ناامیدہوسکتاہوں)اورگمراہوں کے سوااپنے رب کی رحمت سے کون ناامید ہوتاہے تفسیر.حضرت ابراہیم ؑ نے ان کایہ فقرہ سن کر کہ تو ناامید مت ہو.نہایت زوردار الفاظ میں کہا کہ کیا تم مجھے ایساکمزورایما ن والا سمجھتے ہو خدا کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے اورکو ن ناامید ہو سکتا ہے؟مگرمیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھتا ہوں میرے سوال کی غرض تویہ تھی کہ تمہارا مجھے یہ بشارت دینا صرف ایک انسان ڈھکونسلا (جیسے بعض نجومی وغیرہ کہہ دیتے ہیں)یاخدا تعالیٰ کی طرف سے تم کو خبر ملی ہے.جب تم نے یہ بتادیا کہ تم خدا تعالیٰ کی طرف سے خبر پاکر ایساکہہ رہے ہو تومجھے تمہاری بشارت میں کوئی شک نہیں رہا.لَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَکے جواب میں حضرت ابراہیم ؑ کی غیرت ایمانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
Page 332
غیرت ایمانی کودیکھو کہ مایوسی کالفظ سن کر فورً ا جواب دینے کوتیار ہوگئے اوربرداشت نہ کرسکے.ایک طرف ان کی مہمان نوازی اورمہمانوں کی خاطرداری کو دیکھوکہ فوراً گائے ذبح کرکے ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں.اورجب وہ نہیں کھاتے تو ان کے دل میں گھبراہٹ پیداہوجاتی ہے کہ مباداوہ ناراض ہی نہ ہوگئے ہوں.اورمجھ سے کوئی کوتاہی ان کی خدمت میں نہ ہوگئی ہو.لیکن دوسری طرف جب وہی معزز مہمان فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ کہتے ہیں تونہایت جوش اورغیرت سے بول اٹھتے ہیں کہ مومن کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوسکتا.یہ انبیاء کی غیر ت ایمانی کا مقام ہے ہرمومن کو دین کے معاملہ میں ایسی ہی غیرت اپنے دل میں پیداکرنی چاہیے.حضرت ابراہیم ؑکی جگہ اگر کوئی دوسراہوتا توکہتا کہ کیا کروں بوڑھا ہوں میرے قویٰ مضمحل ہوچکے ہیں.اس لئے یقین نہیں آتا مگروہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک بندوں کی طرف سے خبرہو میںاسے قابل تحقیق سمجھتاہوں لیکن اللہ تعالیٰ کی طر ف سے خبرہوتو باوجود مضمحل قویٰ کے میں اس پر پورایقین رکھتا ہوں.قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ۰۰۵۸ (پھر)کہا (کہ اچھا)تواے (خداکے )فرستادو(وہ)تمہارااہم کام کیا ہے(جوتمہارااصل مقصدہے).حلّ لُغَات.الخَطبُ.اَلْـخَطْبُ الشَّانُ.شان.والْاَمْرُ صَغُرَاَوْ عَظُمَ.ہر اہم امر خوا ہ چھوٹا ہو یا بڑا.وَمِنْہُ ھٰذَا خَطْبٌ یَسِیْرٌ وخَطْبٌ جَلِیْلٌ اور خَطْبٌ یَسِیْرٌ اور خَطْبٌ جَلِیْلٌ انہی معنوں میں استعمال ہوتاہے یہ اصلی کام چھوٹاہے اوریہ بڑا.سَبَبُ الْاَمْرِ.کسی امر کاسبب وَقِیْلَ الْخَطْبُ اِسْمٌ لِلْاَمْرِ الْمَکرُوْہِ دُوْنَ المَحْبُوْبِ اوربعض محققین لغت کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ امر کے لئے بطوراسم کے بولاجاتاہے.وَقِیْلَ ھُوَالمَکْرُوْہُ وَالْمَحْبُوْبُ جَمِیْعًا اوربعض کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ امر اورپسندیدہ دونوں کے لئے بولا جاتا ہے.(اقرب) تفسیر.جب یہ معاملہ صاف ہوگیا کہ انہیں نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی میں کوئی کمی نظرآئی تھی اورنہ کوئی بر ی خبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے لائے تھے.توحضرت ابراہیم علیہ السلام نے فورًا سمجھ لیا کہ ان کے آنے کی اصل غرض کچھ اورہے.کیونکہ مجھے بیٹے کی بشارت دینے کے لئے آتے توایسے غمزدہ کیوں ہوتے؟پس معلوم ہوتاہے ان کا پیغام کسی اورشخص کے لئے بھی ہے اور وہی اصل پیغام ہے اورہے بھی غم کا.تبھی یہ کھانانہیں کھاسکے.
Page 333
حضرت ابراہیم کا مہمانوں کے کھانا نہ کھانے سے استدلال پس وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاراخطب کیا ہے.یعنی وہ امر مہم کیا ہے (خطب بڑے اہم امر کوبھی کہتے ہیں اورجواصلی کام ہو بڑاہویاچھوٹااسے بھی.اس جگہ اصل اوراہم کام مراد ہے)جس کے لئے تم آئے ہو تمہارے دل پر جو بوجھ ہے ا س سے ظاہر ہے کہ اصل کام مجھے بیٹے کی بشار ت دینا نہیں اصل کام کوئی اورہے.جو غم پیداکرنے والا ہے.حضرت ابراہیم علیہ السلام کایہ استدلال صاف بتاتا ہے کہ و ہ انہیں انسان سمجھتے تھے تبھی تو باوجود ان کے بشارت دے دینے کے انہوں نے ان کے کھانانہ کھانے کے فعل کو بلاوجہ قرار نہیں دیا.اوراستدلال کیا کہ یہ ضرورکسی اورتکلیف دہ امر کے لئے سفرکررہے ہیں اگر وہ اس بشارت کی وجہ سے ان کو فرشتہ خیال کرلیتے توکھانانہ کھانے کاسوال بھی ان کے لئے حل ہوجاتا.وہ اگلا سوال ان سے کیونکر کرسکتے تھے.کہ پھر تمہارااصل مشن کیا ہے؟ یہ امر کہ ان کاکوئی اورمشن بھی ہے صرف کھانانہ کھانے سے ہی سمجھاجاسکتاہے.اوراسی وقت سمجھا جاسکتاتھا جبکہ انہیں انسان سمجھا جاتا.ابراہیم نے کہا کہ تمہارے دل پر کسی امر کابوجھ ہے جس کی وجہ سے تم کھاناوغیرہ نہیں کھاسکتے.قَالُوْۤا اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَۙ۰۰۵۹ انہوں نے کہا (کہ)ہمیں یقیناً ایک مجرم قوم کی طرف (ان کی ہلاکت کے لئے )بھیجا گیاہے.تفسیر.انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے عذاب کی خبردیں اس لئے ہمارے دل پر بوجھ ہے.اِلَّاۤ اٰلَ لُوْطٍ١ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَۙ۰۰۶۰ سوائے لوط کے پیرئووں کے (کہ)ان سب کو ہم یقیناً بچالیں گے.تفسیر.لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط ؑ کے ساتھ نجات پانے والی ایک جماعت تھی ہاں لوط کاخاندان مستثنیٰ ہے اس فقرہ سے انہوں نے قو م بھی ظاہرکردی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر تسلی دے دی تاحضرت لوط کی وجہ سے غمگین نہ ہوں اوریہ جو فرمایا ہم ان سب کو نجات دیں گے یہ میرے نزدیک اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت لوط کی آئندہ رہائش کے انتظام کے لئے
Page 334
بھیجاتھا.بائبل اور قرآن مجید میں اختلاف لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت لوط کے ساتھ نجات پانے والے لو گ قرآن مجید کے نزدیک ایک جماعت تھے بائبل نے صرف ان کی دولڑکیوں کے بچنے کا ذکر کیا ہے (پیدائش باب ۱۹ آیت ۳۰)حالانکہ آل لوط اگر دولڑکیوں پر مشتمل تھے تو اجمعین کالفظ ان کے لئے نہیں بولاجاسکتا.اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَاۤ١ۙ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَؒ۰۰۶۱ اس کی بیوی کے سوا (کہ)ہمارااندازہ ہے کہ وہ یقیناً پیچھے رہنے (اورہلاک ہونے )والوں میں سے ہوگی.حلّ لُغَات.قَدَّرْنَا.قدرنا قَدَّرَ کالفظ جب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تواس کے معنے فیصلہ کرنے کے ہوتے ہیں اور جب کسی انسان کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی اندازہ اورقیاس کرنے کے ہوتے ہیں.چنانچہ مفردات میں لکھاہے التَّقْدِیْرُ تَبْیِیْنُ کَمِیّۃِ الشَّیْءِ.تقدیر کے معنی ہیں کسی چیز کی کمیت کوواضح کرنا اورجب اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تواس کے معنے ہوں گے تَقْدِیْرُاللہِ بِالْحُکْمِ مِنْہُ اَنْ یَّکُوْنَ کَذَااَوْلَایَکُوْنَ کَذَاکہ اللہ تعالیٰ کاکسی معاملہ کے متعلق فیصلہ کرنا کہ وہ اس طرح ہو یااس طرح نہ ہو اورجب کسی انسان کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تومعنے ہو ں گے اَلتَّفَکُّرُ فِی الْاَمْرِ بِحَسَبِ نَظَرِ الْعَقْلِ وَبِنَاءُ الْاَمْرِ عَلَیْہِ کہ کسی معاملہ میں عقل کے ساتھ غوروفکرکرکے اس کااندازہ لگایاجائے اوراس پر کسی کام کی بناء رکھی جاوے.(مفردات) الغَابِرُ.الغَابِرُ الْبَاقِیْ.غَابر کے معنی ہیں باقی رہنے والا.اس کی جمع غُبَّرٌ اورغَابِرُوْنَ آتی ہے.وَمِنْہُ فَانْجَیْنٰہُ وَ اَھلَہُ اِلَّاامْرَأَتَہُ کَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِیْنَ.اَیْ مِنَ الَّذِیْنَ بَقَوْا فِی دِیَارِھِمْ فَھلَکُوْا اورآیت اِمرأَتُہٗ کَانَتْ مِنَ الغٰبِرِیْنَ.میں لفظ غابر باقی رہنے والے کے معنوں میں ہی استعمال ہواہے.یعنی ان کی بیوی ان لوگوں میں سے تھی جو شہر میں پیچھے رہ گئے تھے.(اقرب) تفسیر.قَدَّرْنَاکے الفاظ کہنے سے مراد ’’اندازہ‘‘ کرنا ہے یعنے آل لوط میں سے ان کی بیوی چونکہ خو د پیچھے رہ جائے گی اس لئے وہ نہ بچائی جائے گی یہ لوگ قَدَّرْنَاۤ کالفظ استعمال کرتے ہیں جس کے معنے مقررکرنے کے بھی ہوتے ہیں.اس لئے بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا ہے.کہ وہ فرشتے تھے ورنہ قَدَّرْنَاکیونکر کہتے؟ لیکن یہ درست نہیں.کیونکہ اگروہ فرشتے بھی ہوتے توبھی قدّرناکیونکر کہہ سکتے تھے.تقدیر تو
Page 335
اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نہ کہ فرشتوں کے.پس قدّرنا کے اس جگہ یہ معنے نہیں کہ ہم نے ایسا فیصلہ کیا ہے بلکہ اس کے معنی اس جگہ اندازہ لگانے کے ہیں.معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یاان میں سے کسی ایک کو خواب یا الہام میں جو خبر دی گئی تھی اس میں بیوی کے متعلق گووضاحت نہ تھی مگر استدلال یہی ہوتاتھا کہ وہ نہ بچے گی.پس انہوں نے اللہ تعالیٰ کے الہام کا ادب کرتے ہوئے اس پر زیادہ زورنہ دیااوراسی قدرکہا کہ ہمارااندازہ الہام الٰہی سے یہی ہے کہ وہ نہ بچے گی.یایہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلی کے لئے اس مضمون پر زیادہ زورنہ دیا اوریہ جھوٹ نہیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر کردہ عذابوںکو بدل بھی دیتاہے.ممکن ہے ان کے دل میں خیال ہو کہ شائد حضرت لوط کی دعاسے بیوی کایہ عذاب ٹل جائے.پس انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی الفاظ میں خبردینی مناسب سمجھی کہ ہمارااندازہ یہ ہے کہ وہ حضرت لوط کے ساتھ نہ جائے گی.دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف بھی منسوب فرمایا ہے چنانچہ فرماتا ہے.قَدَّرنٰھَامِنَ الغٰبِرِیْنَ.(النمل :۵۸) اب یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ ادھرخدا تعالیٰ کہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیاتھا اورادھر وہ رسول یا فرشتے جوکچھ بھی چاہو انہیں کہہ لو.وہ کہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے.اللہ تعالیٰ اور انسان کے لئے قدّر کے لفظ کے استعمال میں فرق پس حقیقت یہ ہے کہ جیساکہ لغت میں ہے.جب خدا تعالیٰ کی نسبت یہ لفظ آتاہے وہاں فیصلہ کرنے کے معنے ہوتے ہیں اور جب انسانوں کی نسبت آتا ہے وہاں اندازہ یاقیاس کرنے کے معنے ہوتے ہیں.ان لوگوں کے قول میں اس کے معنے اندازہ یاتخمین سے بات کرنے کے ہیں.حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بچانے کے متعلق قرآن مجید اور بائیبل کا اختلاف بائبل کے بیان اورقرآن کریم کے بیا ن میں یہاں بھی اختلاف ہے بائبل میں لکھا ہے ’’جب صبح ہوئی فرشتوں نے لوط سے تاکید کر کے کہا کہ اُٹھ اپنی جورو اوراپنی دوبیٹیاں جو یہاں موجو د ہیں لے ‘‘(پیدائش باب ۱۹ آیت ۱۵) اورپھر آیت۱۶ میں بیان ہے کہ حضر ت لو ط نے کچھ دیر کی توانہوں نے’’ اس کا اوراس کی جورو کااور اس کی دونو ں بیٹیوں کاہاتھ پکڑا کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی.اوراسے نکال کر شہر سے باہر پہنچادیا.‘‘لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضر ت لوط کو پہلے ہی خبردے دی گئی تھی کہ وہ ساتھ نہ جائے گی بلکہ پیچھے رہ جائے گی.قرآن مجید میں حضرت لوط کی بیوی کے پیچھے رہنے کا ذکر چنانچہ فرماتا ہے جب رسول حضرت لوط کے پاس آئے توانہوں نے حضرت لوط سے کہا.اِنَّا مُنَجُّوْکَ وَاَھْلَکَ اِلّاامْرَاَتَکَ کَانَتْ مِنَ الغٰبِرِیْنَ (العنکبوت:۳۴) یعنے ہم تجھے اورتیرے اہل کوتویہاں سے بچاکرلے جائیں گے مگر تیری بیوی کو نہیں وہ پیچھے رہنے والے گروہ میں ہوگی.
Page 336
اب ہرعقل مند خود سمجھ سکتاہے کہ کون سابیان عقل کے مطابق ہے.کیاقرآن کریم کاجو کہتاہے کہ وہ پیچھے ہی رہ گئی تھی یابائبل کا جو کہتی ہے کہ فرشتوں نے پکڑ کر ان کی بیوی کو شہر سے باہر نکالا؟سوال یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس عورت نے تباہ ہونا ہے توا سے پکڑ کرباہر نکالنے کے معنے کیاتھے ؟جس کے متعلق تباہی کافیصلہ تھا اسے فرشتوں نے نکالا کیوں.کوئی آدمی باہر نکالتا توکہہ سکتے تھے کہ اسے علم نہ تھا.لیکن فرشتے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے خبرلے کر آئے تھے باوجود اس علم کے کہ اس عورت نے تباہ ہونا ہے اسے کیوں باہر نکالنے لگے.فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ا۟لْمُرْسَلُوْنَ۠ۙ۰۰۶۲ پھر جب وہ (ہمارے)بھیجے ہوئے (لوگ)لوط (اوراس)کے اتباع کے پا س آئے قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ۰۰۶۳ تواس نے (انہیں)کہا (کہ)آپ (اس علاقہ میں) اجنبی (معلوم ہوتے)ہیں.حلّ لُغَات.مُنْکَرُوْن.مُنْکَرُوْنَ اَنْکَرَ سے اسم مفعول مُنْکَرٌ بنتاہے اورمُنْکَرُوْنَ اس کی جمع ہے.اَنْکَرَہُ کے معنی ہیں جَہِلَہٗ اس کونہ پہچانا.اَنْکَرَ حَقَّہٗ کے معنی ہیں.جَحَدَہٗ اس کے حق کاجان بوجھ کر انکار کردیا.اَنْکَرَ عَلَیْہِ فِعْلَہُ: عَابَہَ وَنَھَاہُ اس کے فعل کومعیوب قرار دیا اوراس سے اُسے روکا.المُنْکرُ کے معنی ہیں مَالَیْسَ فِیْہِ رِضَی اللّٰہِ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ وَالْمَعْرُوْفُ ضِدُّہٗ.منکر وہ فعل یاقول ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اورلفظ معروف (پسندیدہ) اس کے مخالف معنے اداکرنے کے لئے بولاجاتاہے (اقرب)پس اِنَّکُمْ قَوْمٌ مُّنْکَرُوْنَ کے ایک معنی ہوئے کہ آپ اس علاقہ میں انجان یااجنبی معلوم ہوتے ہیں.تفسیر.مرسلون کے لفظ سے بھیجے ہوؤں کا انسان ہونا ثابت ہوتا ہے قرآن کریم انہیں پھر مُرْسَلُوْن کہہ کر ان کے انسان ہونے کی طر ف اشارہ فرماتا ہے.بائبل کا عجیب حال ہے کہ کبھی انہیں مردکہا ہے (پیدائش باب ۱۸آیت ۲،۱۶) اور کبھی فرشتے(پیدائش باب ۱۹ آیت ۱)اورباوجود فرشتہ کہنے کے لکھا ہے کہ حضرت لوط نے ان کے لئے فطیری روٹی پکائی اورانہوںنے کھائی( پیدائش باب ۱۹آیت ۳ ) فرشتوں کا فطیری روٹی کھانا ایک عجوبہ ہے اوراس پر دلالت کرتا ہے کہ تورات میں بعد میں بہت کچھ رطب ویابس شامل کردیاگیا ہے.
Page 337
قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ۰۰۶۴ انہوں نے کہا (کہ ایسا)نہیں بلکہ ہم (تو)تمہارے پاس (ہی )آئے ہیں (اور)وہ چیز لے کر(آئے ہیں)جسکے متعلق یہ (لوگ)شک کرتے رہے ہیں.حلّ لُغَات.یَمْتَرُوْن.یَمْتَرُوْنَ اِمْتَرٰی سے مضارع جمع غائب کاصیغہ ہے اور اِمْتَرٰی فِی الشَّیْءِ کے معنے ہیں شَکَّ فِیہِ: کسی چیز میں شک کیا(اقرب) پس بَلْ جِئْنَاکَ بِمَاکَانُوْا فِیْہِ یَمْتَرُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے متعلق یہ لو گ شک کرتے رہے ہیں.تفسیر.حضرت لوطؑ نے جب کہا کہ آپ تو مسافر اورراہگیر معلوم ہوتے ہیں.توانہوں نے کہا ہم راہگیرنہیں ہیں بلکہ ایک غرض کے لئے تیرے پاس آئے ہیں.اوراس چیز کی خبر لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں یعنی عذاب کی خبر لے کرآئے ہیں.حضرت لوط ؑ کی قوم کو عذاب کی خبر مرسلوں کے آنے سے پہلے مل چکی تھی اس سے معلوم ہوتاہے کہ عذاب کی خبر لوط کی قوم کو حضرت لوط کے ذریعہ سے مل چکی ہوئی تھی.کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بتانے کے لئے آئے ہیں کہ اب عنقریب ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں.گویا عذاب کی خبر توپہلے ہی اس قوم کو دی جاچکی تھی.اب یہ لوگ حضرت لوط کو صرف یہ بتانے کے لئے آئے تھے کہ اب اس موعود عذاب کا وقت آگیا ہے.آپ یہاں سے ہمارے ساتھ چل پڑیں.وَ اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ۰۰۶۵ اورہم تمہارے پاس یقینی خبر لائے ہیں اورہم یقیناً سچے ہیں.حلّ لُغَات.بِالْحَقِّ.بِالْحَقِّ الحق کے معنی ہیں یقینی خبر.مزید تشریح کے لئے دیکھو سورۃ رعد آیت نمبر ۱۵ جلد ھذا.تفسیر.مرسلوں کا الحق کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ چونکہ حضرت ابراہیم نے سوال کیاتھا کہ تم مجھے کس بناء پر بشار ت دیتے ہو وہ خود ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت لوط کو بھی شک ہو گا.کہ یہ لوگ کون ہیں اورکیوں آئے ہیں؟ اس لئے انہوں نے آپ ہی بتادیا.کہ ہم الحق کے ساتھ آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے
Page 338
ساتھ اورپھر اِنَّالَصٰدِقُوْن کہہ کر زوردیا کہ ہم پر بدگمانی نہ کریں.ہم اس دعویٰ میں سچے ہیں.فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ اتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَ سوتم رات کے آخری حصہ میں (کسی وقت )اپنے گھروالوں کو لے کر (یہاں سے )چلے جائو.اور(خود)ان کے لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّ امْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ۰۰۶۶ پیچھے (پیچھے)رہو اور تم میں سے کوئی ( اِن کی طرف )التفات(ظاہر)نہ کرے اورجہاں(جانے )کاحکم تمہیں دیاجاتاہے (سب وہاں)چلے جائو.حلّ لُغَات.اَسْرِ بِاَھْلِکَ.اَسْرِ سَرَی سے باب افعال کاصیغہ امر ہے اورسَرَی الرَّجُلُ کے معنی ہیں سَارَ عَامَّۃَ اللَّیْلِ رات کا اکثر حصہ چلا.اَسْری الرَّجُلُ اِسْرَاءً مِثْلُ سَرَی.اور اَسْرَی (باب افعال ثلاثی مزید)کے معنے سَرَی (ثلاثی مجرّد )کے ہی ہیں.وَقِیْلَ اَسْرَی لِاَوَّلِ اللَّیْلٍ وَسَرَی لِاَخِرِ اللَّیْلِ.اوربعض محققین لغت کہتے ہیں کہ اَسْرَی کافعل رات کے ابتدائی حصہ میں چلنے کے متعلق استعمال ہوتاہے.اورسَرَی کا فعل رات کے آخری حصہ میں چلنے پر.اَسْرَاہ واَسْرَی بِہِ (متعدی)کے معنی ہیں.سَیَّرَہٗ باللّیْلِ اَیْ سَیَّرہُ لَیْلًا یعنےاسے رات کو روانہ کیا.(اقرب) قِطْعٌ مِّنَ اللَّیْلَ: قِطْعٌ کے معنی ہیں ظُلْمَۃُ آخَرِ اللَّیْلِ رات کے آخری حصہ کی تاریکی.وَقِیْلَ من اوّلِہٖ الیٰ ثُلثِہٖ اوربعض کے نزدیک رات کے ابتدا سے لے کر رات کے تیسرے پہر کی تاریکی کے لئے یہ لفظ بولاجاتاہے.(اقرب) اس اختلاف کے لحاظ سے اَسْرِ بِاَھْلِکَ کے معنے ہوں گے کہ رات کے کسی حصہ میں یا ابتدائی یاآخری حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلو.لیکن رات کے آخری حصہ میں جانازیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ اگلی آیت میں مُصْبِحِیْنَ کالفظ استعمال ہواہے.اس لحاظ سے معنے یہ ہوں گے کہ رات کے آخری حصہ میں کسی وقت اپنے گھروالوں کو لے کر چلو.اگر اَسْرِ سے رات کے آخر ی حصہ میں چلنا مراد لیں.تو بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّیْلِ اس کی تشریح ہوگی.تفسیر.ان مرسلوں نے حضرت لوط ؑکو ان کے نکلنے کے متعلق تفصیلات سے اطلاع دی.اوربتایا کہ رات کے آخری حصہ میں یہاں سے نکلیں.گووضع لغت کے لحاظ سے اِسراء رات کے کسی حصہ میں جانے کے متعلق
Page 339
بولاجاتاہے.لیکن بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّیْلِ سے معلوم ہوتاہے کہ حضرت لوط کو رات کے آخری حصہ میںنکلنے کو کہاگیاہے کیونکہ وہ کہتے ہیں جب رات کاایک حصہ باقی رہ گیاہو تب نکلو.اس احتیاط میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ تادشمن پیچھانہ کرسکیں.کیونکہ جس وقت انہیں نکلنے کوکہاگیاہے.اس کے معاًبعد عذاب آنے والاتھا.پس اگر ان لوگوںکو حضرت لوط کے نکلنے کے کچھ دیر بعد پتہ بھی لگ جاتا.تووہ پیچھا نہیں کرسکتے تھے.حضرت لوط ؑ کو قافلہ کے پیچھے رہنے کے حکم کا مطلب یہ جوکہاکہ توان سب کے پیچھے رہیو.اس میں رحم کا پہلو ہے کیونکہ عذاب سے اصلی حفاظت نبی کو حاصل ہوتی ہے جب تک حضرت لوط عذاب سے محفوظ نہ ہوتے عذاب نہیں آسکتاتھا.پس انہوں نے ہدایت کی کہ قافلہ کی کامل حفاظت اسی میں ہے کہ آپ سب کے پیچھے رہیں تاساراقافلہ عذاب سے کلی طور پر محفوظ ہوجائے.حضرت لوط ؑ کے ساتھ نکلنے والوں کے متعلق بائیبل اور قرآن مجید میں اختلاف اس آیت سے قطعی طور پر ثابت ہوتاہے کہ حضرت لوط ؑپرکچھ لوگ ایمان ضرورلائے تھے.گوبائبل صرف یہ کہتی ہے کہ ان کی دولڑکیاں ان کے ساتھ نکلی تھیں اور کوئی نہیں(پیدائش باب۱۹آیت ۱۶)مگرقرآن کریم اس کے خلا ف کہتا ہے.کیونکہ اس آیت میں فرماتا ہے.وَ اتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ نکلنے والے قافلہ کے پیچھے رہو.اَدْبَارَهُمْ میں ھم کی ضمیر بتاتی ہے کہ حضرت لوط کے ساتھ ایک جماعت تھی اور ھُمْ کالفظ استعمال فرمایا ہے.جوتین یاتین سے زیادہ مردوں کے لئے ستعمال ہوتاہے.یامردوںاورعورتوں کی مخلوط جماعت کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ جب مرد اورعورت اکٹھے ہوں.تومذکر کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے لیکن اگر مرد تھے ہی نہیں جیساکہ بائبل کہتی ہے تو وَاتَّبِعْ اَدْبَارَھُمَا چاہیے تھا یااگردوسے زیاد ہ عورتیں تھیں تو اَدْبَارَھُنَّ کہناچاہیے تھا.لیکن صرف دولڑکیوںکے لئے اَدْبَارَھُمْ کسی صورت میں استعمال نہیں ہوسکتا.پس اس آیت سے قطعی طورپر ثابت ہے کہ حضرت لوط کے ساتھ نکلنے والے کچھ اورمرد تھے اس وجہ سے عورتوں اورمردوں کے مخلوط قافلہ کو ھُمْ کی ضمیر سے یاد کیاگیا.بائیبل میں حضرت لوط کے ساتھ نکلنے والی صرف ان کی دو لڑکیاں بتائی گئی ہیں گوبائبل میں نکلنے کاواقعہ جہاں بیان ہواہے وہاں صرف دولڑکیوں کا ذکر ہے لیکن ایک اورجگہ سے بائبل سے بھی استدلال ہوتاہے.کہ بائبل کایہ بیان غلط ہے اوروہ اس طرح کہ بائبل میں جہاں ان مرسلوں کے آنے کا ذکر ہے وہاں لکھاہے کہ حضرت ابراہیم نے ان کے جانے کے بعد اللہ تعالی سے دعاکی کہ کیا اگر پچاس راستباز وہاں ہوں تواس قوم کو ان کی
Page 340
خاطرنہ بچائے گااللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر پچاس صادق ہوں تومیں ان کی خاطرسارے شہر کو چھوڑ دوں گااس پرحضرت ابراہیم علیہ السلام تعداد کم کرتے گئے حتی کہ آخر میں دس صادقوں کے ہونے پر بھی شہر کو بچالینے کی درخواست کی اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دس صادق بھی ہوں تب بھی میں شہر کو بچا لوں گا.تب حضرت ابراہیم خاموش ہوگئے اورسمجھ لیا کہ دس صادق بھی ا س شہرمیں نہیں ہیں(پیدائش باب۱۸ آیت ۲۲تا۳۲) حضرت لوط ؑ پر ایمان لانے والی ایک جماعت تھی اس واقعہ سے معلوم ہوتاہے کہ حضر ت ابراہیم ؑ کویہ معلوم تھاکہ کچھ لوگ حضرت لوط پرایمان لائے ہیں ورنہ وہ یہ دعاکیوں کرتے.حضرت لوط ؑ تھوڑے ہی فاصلہ پر رہتے تھے اوریقیناًان کی خبریں حضرت ابراہیم ؑکو ملتی رہتی ہوں گی.پس یہ کیونکر ہوسکتاتھاکہ اگران کے علم میں کوئی بھی مومن نہ تھاتووہ ایسی دعاکرتے.ہاں یہ معلوم ہوتاہے کہ انہیں اتنا معلوم تھاکہ مومنوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے اسی لئے انہوں نے پچاس کے عدد سے دعاشروع کی اوردس پر آکر چھوڑ دی.اس سے معلوم ہوتاہے کہ دس سے کم مومن تھے.اور چونکہ تین یا تین سے زیادہ پر ھُمْ کالفظ بولاجاتاہے.اس لئے ممکن ہے تین یا دوچار زیادہ مومن ہوں.لَا يَلْتَفِتْ کہنے سے مراد کفار کی طرف توجہ نہ کرنا ہے اوریہ جو فرمایاکہ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اس سے مراد پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں بلکہ یہ ہے کہ کفارکی طرف توجہ نہ کرو.اورانہیں ہلاک ہونے دو.ورنہ پیچھے مڑکردیکھنے میں کوئی خاص بات نہ تھی.حضرت لوط ؑ کی بیوی کے متعلق بائبل کا ایک عجیب بیان بائبل میں لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے مڑ کردیکھا اوروہ نمک کا کھمبابن گئی (پیدائش باب ۱۹ آیت ۲۶).یہ کہ وہ نمک کاکھمبابن گئی.اسے تومیں یہود اور مسیحیوں کی عقل پر چھوڑتاہوں مگر یہ میں واضح کر دینا چاہتاہوں کہ قرآن کریم کے روسے ان کی بیوی ساتھ آئی ہی نہ تھی.کیونکہ فرماتا ہے.کَانَتْ مِنَ الْغَابِرِیْنَ وہ پیچھے ہی رہ گئی تھی.پس قرآن کریم کے بیان کے روسے اس کے نمک کاکھمبابن جانے یاکچھ اوربن جانے کاسوال ہی نہیںپیدا ہوتا.اس کی قسم کی لغویت سے قرآنی بیان کاپاک ہونا ثابت کرتاہے کہ وہ خدائی کلام ہے.ورنہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ تورات جو قریب کے زمانہ میں لکھی گئی و ہ توایسے لغو قصہ کو بیان کرتی ہے مگر قرآن کریم اسے چھوڑ دیتاہے.وَامْضُوْا حَیْثُ تُؤمَرُوْنَ سے میرے اس دعویٰ کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضرت لوط کو وہ لوگ یہ بتانے کے لئے آئے تھے کہ وہاں سے نکل کر وہ کہاںجائیں اوراس کام میں مدد دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کرکے
Page 341
بھیجاتھا.ان کو سب نشان پتہ بتاکر معلوم ہوتاہے وہ لو گ چلے گئے اورکہہ گئے کہ ہماری بتائی ہوئی جگہ پر آجانا کیونکہ وہیں آپ کا آنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے مقدرکیاہے.وَ قَضَيْنَاۤ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ اوریہ بات ہم نے اسے یقینی طورپربتادی ہے کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے (ہی) مُّصْبِحِيْنَ۰۰۶۷ کاٹ دی جائے گی.حلّ لُغَات.قَضَیْنَا.قَضَیْنَا قَضٰی سے جمع متکلم کاصیغہ ہے اورقَضٰی بَیْنَ الْخَصْمَیْنِ کے معنی ہیں حَکَمَ وَفَصَلَ.مدعی اورمدعاعلیہ کے درمیان جھگڑے کافیصلہ کردیا.قَضَی الشَّیْءَ قَضَاءً.صَنَعَہٗ بِاِحْکَامٍ وَقَدَّرَہٗ.کسی چیز کو عمدہ طورپر بنایا.اورا س کاصحیح اندازہ لگایا.قَضَی الْاَمْرَ عَلَیْہِ.خَتَمَہٗ وَاَوْجَبَہٗ وَاَلْزَمَہٗ بِہٖ.اس کے خلاف بات کو ختم کردیا اوراس پر اس کوواجب کر دیا اوراس کاپوراکرنا ا س کا فرض قرار دیا.اَلشَّیئَ.اَعَلَمَہٗ و بَیَّنَہُ کسی معاملہ کا اعلان کیا اور اس کو کھول کر بیان کیا.قَضَی لَکَ الْاَمْرَاَی حَکَمَ لَکَ کسی معاملہ کاتیرے حق میں فیصلہ کردیا (اقرب)پس قَضَیْنَا اِلَیْہِ کے معنے ہوں گے کہ ہم نے یہ بات کھلے طورپر بتادی.الدَّابِرُالدَّابِرُکے معنی ہیں التَّابِعُ.تابع.آخِرُ کُلِّ شَیْ ءٍ ہرچیز کاآخری حصہ.یُقَالُ قَطَعَ اللّٰہُ دَابِرَھُمْ اَیْ آخِرَ مَنْ تَبَقَّی مِنْھُمْ اورقَطَعَ اللّٰہُ دَابِرَھُمْ میں دابر آخر کے معنوں میں ستعمال ہواہے.یعنی اللہ نے ان میں سے سب سے پیچھے رہنے والے کو بھی تباہ کردیا.اَلْاَصْلُ جڑھ(اقرب)الغرض دابر سے مراد کبھی جڑ ھ ہوتی ہے یعنی بڑے لوگ.کیونکہ وہ بطور جڑھ کے ہوتے ہیں اورباقی لوگ بطور فرع کے.اور کبھی دابر سے مراد ساری قوم ہوتی ہے اوریہاں پر سب قوم ہی مراد ہے کیونکہ صرف آل لوط کے بچائے جانے کی خبر ہے.تفسیر.یہ آیت خدا تعالیٰ کاکلام معلوم ہوتی ہے ان مرسلوں کاقول نہیں.اوریہ بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ آیت بھی اللہ تعالیٰ کاکلام ہو.مگر یہ آیت ضرور اللہ تعالیٰ کاکلام ہے جومعلوم ہوتاہے.ان مرسلوں کی صداقت پر گواہی دینے کے لئے حضرت لوط ؑپر نازل ہوا.اورانہیں بتایاگیا کہ ان لوگوں نے جو تم کو بتایا ہے کہ آج رات کے آخر پر عذاب آئے گا.یہ درست ہے.ہماری ہی بتائی ہوئی یہ خبرہے.اورصبح کے وقت ضرور یہ قوم تباہ ہوجائے
Page 342
گی.دَابِر ھٰؤُلَآئِ سے یہ مراد ہے ان کا آگاپیچھا کچھ بھی باقی نہ رہے گا.وَ جَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ۠۰۰۶۸ اور(ادھر)اس شہر کے لوگ خوشیا ں مناتے ہوئے (اس کے پاس )آئے.حلّ لُغَات.المدینۃ:المَدِیْنَۃُ مَدَنَ سے اسم ہے اورمَدَنَ بِالْمَکَانِ کے معنی ہیں اَقَامَ.کسی جگہ ٹھہرا.اوراَلْمَدِیْنَۃُ کے معنی ہیں الْمِصْرُالْجَامِعُ بڑاشہر.وَقِیْلَ الْحِصْنُ یُبْنٰی فِیْ اُصْطُمَّۃِ الْاَرْضِ.وہ قلعہ جو کھلی فراخ زمین میں بنایاجاوے.(گویا اردگرد کے لئے مرکز کاکام دے ).(اقرب) تفسیر.حضرت لوط کی بستی کو مدینہ کہے جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہم بستی تھی اس بستی کو مدینہ کہہ کر پکاراگیاہے.معلوم ہوتاہے اہم بستی تھی.چنانچہ بائبل سے معلوم ہوتاہے کہ یہ شہر چند بستیوں کا مرکز تھا(پیدائش باب ۱۹ آیت ۱۸.۳۱).یَسْتَبْشِرُوْنَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ خوش ہوئے کہ اب حضرت لوط کو ملزم بناسکیں گے اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ ان مردوں سے بدکاری کرنے کی خواہش کی وجہ سے وہ خوش تھے.جیساکہ مفسرین نے لکھا ہے.کیا اس بستی میں مر دنہ ہوتے تھے کہ باہرسے آنے والوں کی خبر سن کر وہ خوش ہوگئے (تفسیر بغوی زیر آیت ھذا).قَالَ اِنَّ هٰؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِۙ۰۰۶۹ (جس پر )اس نے (ان سے)کہا (کہ )یہ لوگ یقیناً میرے مہمان ہیں.اس لئے تم(انہیں تکلیف دے کر)مجھے رسوانہ کرو.حلّ لُغَات.تَفْضَحُوْنِ:تَفْضَحُوْنَ فَضَحَ سے جمع مخاطب کے مضارع کاصیغہ ہے اور فَضَحَ کے معنے ہیں.کَشَفَ مَسَاوِئَہُ.اس کے عیوب کو ظاہر کیا.وَفِی الدُّعَاءِ لَاتَفْضَحْنَا بَیْنَ خَلْقِکَ اَیْ أُسْتُرْعُیُوْبَنَا وَلَا تَکْشِفَہَا عَنَّا(اقرب)اوردعائے مسنونہ میں جو فَضَحَ کالفظ استعمال ہواہے اس کے معنی ہیں کہ اے خدا!ہمارے عیوب پرپردہ پوشی کر اوران کو ظاہر نہ کر(اقرب)پس فَلَا تَفْضَحُوْنِ کے معنے ہوں گے تم میری کمزوریوں کو ظاہرکرکے مجھے رسوانہ کرو.
Page 343
تفسیر.جب شہرکے لوگ حضرت لوط ؑ کے پاس پہنچے تو حضرت لوط ؑ جن کو وہ لوگ باہر کے آدمی لاکرمہمان رکھنے سے منع کیاکرتے تھے سمجھ گئے کہ اب یہ قوم مجھے ملزم قرار دے گی.اورانہوں نے الگ ہو کر ان سے کہا.کہ اب تومیں مہمان لے آیاہوں.اب تم مجھے مہمانوں کے سامنے ان کی ضیافت پرزجر کرکے نادم نہ کرو.وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ۰۰۷۰ اوراللہ (تعالیٰ) کاتقویٰ اختیارکرو اورمجھے ذلیلنہ کرو.حلّ لُغَات.تُخْزُونِ:تُخْزُوْنِ اَخْزَی سے مضارع جمع مخاطب کاصیغہ ہے اوراَخَزَاہُ اِخْزَاءً کے معنے ہیں اَوْقَعَہٗ فِی الْخِزْیِ اَوِالْخَزَایَۃِ واَھَانَہٗ.کہ اس کو ایسے معاملہ میں پھنسایا جس سے اُسے ندامت ہو اوراسے رسواو ذلیل کیا (اقرب)فَلَا تُخْزُونِ کے معنے ہوں گے کہ تم مجھے ذلیل نہ کرو.تفسیر.اللہ کاتقویٰ اختیار کرو.یعنے مہمان نوازی ایک نیک فعل ہے.اس پر اعتراض نہ کرو اورمہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو.قَالُوْۤا اَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ۰۰۷۱ انہوں نے کہا اور کیا ہم نے تمہیں (بیرونی)لوگوں (کو اپنے پاس ٹھہرانے )سے روکا نہ تھا.تفسیر.حضرت لوط ؑ کی قوم کا ان کو کسی مہمان کے پاس لانے سے روکنے کی وجہ اس زمانہ میں ان بستیوںاور دوسری بستیوں میں کچھ جھگڑے تھے.اوروہ ڈرتے تھے کہ باہر سے آدمی آکر شہر پر حملہ نہ کروادیں.اس لئے وہ لوگ حضرت لوط ؑ کو اجنبی مہمان لانے سے روکتے رہتے تھے (پیدائش باب ۱۴ آیت ۱۱).مگرچونکہ علاقہ خطرناک تھا.حضرت لوط ؑکو جب اجنبی ملتے وہ انہیں اپنے گھر لے آتے تارات کو وہ راستہ پر لٹ نہ جائیں.اس دفعہ جو وہ مہمان لائے اس شہر والوں نے فیصلہ کیا کہ اب کے ضرور لوط(علیہ السلام) کی اچھی طرح خبر لینی چاہیے اور چونکہ حضرت لوط کو کسی بہانہ سے بستی سے نکالناچاہتے تھے وہ خوش بھی ہوئے کہ اب یہ قابو آگئے ہیں اب ہم ان کو یہاں سے چلے جانے پرمجبورکرسکیں گے ان کا یہ تردّد اس لئے تھاکہ حضر ت لوط کی بیٹیاں وہاں بیاہی ہوئی تھیں اوراس وجہ سے وہ شہر کے ساکن تھے اورانہیں بلاوجہ نہیں نکالاجاسکتاتھا.اس آیت سے ظاہر ہے کہ وہ
Page 344
لوگ ان مردوں سے بدکاری کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے.اگر وہ اجنبیوں سے ایسے فعل کیاکرتے تھے تووہ یہ نہ کہتے کہ جب ہم نے منع کیا ہواہے کہ اجنبی آدمی نہ لایا کرو.پھرتُوکیوں اجنبیوں کولایا؟تب تو انہیں حضرت لوط کے مہمان بلانے پر خوش ہوناچاہیے تھا.نیز یہ کیسی عقل کے خلا ف بات ہے کہ پہلے توکبھی انہوں نے مہمانوں سے ایسافعل نہ کیا.بلکہ صرف مہمان لانے سے روکتے رہے لیکن اس دن بدکاری پر تیار ہوگئے اصل با ت یہ ہے کہ یہ خیال بالکل خلاف عقل ہے.کہ وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے اوربائبل سے لے کر بعض مفسرین نے نقل کردیا ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ شہر کے لوگ ان فرشتوں سے بدکاری کرنا چاہتے تھے (پیدائش باب۱۹ آیت ۵) حالانکہ بائبل میں ایسی رطب و یابس باتیں بہت سی درج ہیں او راس کے بہت سے مضامین متضاد ہیں.اس کے بیان کی جب تک قرآن کریم یاصحیح تعریف یا عقل سے تائید نہ ہوتی ہو.اعتبار کرناسخت خطرناک ہے.قَالَ هٰؤُلَآءِ بَنٰتِيْۤ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَؕ۰۰۷۲ اس نے کہا (کہ )اگرتم نے (میرے خلاف )کچھ کرنا (ہی)ہوتو یہ میری بیٹیاں(تم میں موجود ہی)ہیں.تفسیر.اس آیت کو اوپر کے لغو خیا ل کی تائید میں دلیل سمجھاجاتاہے لیکن یہ دلیل دعویٰ سے بھی لُچر ہے.ایک طرف تو ان لوگوں کو مردوں سے بدکاری کا شائق قرار دیاجاتاہے.اورکہاجاتاہے کہ وہ ان مردوں سے بدکاری کرنے کے شوق میں آئے تھے اوردوسری طرف یہ کہاجاتاہے کہ حضرت لو ط نے کہا کہ اگر بدکاری کاشوق ہے تومیری بیٹیاں حاضر ہیں.اگر ان لوگو ں کو عورتوں سے مباشرت کا شوق ہوتا.توکیاان کے گھر میں بیویاں نہ تھیں وہ اس طرح ان کے پاس کیوں دوڑے آتے اوراگر وہ مردوں سے بدکاری کی نیت سے آئے تھے توپھر حضرت لوط ؑ کے اس قول کے کیامعنے ہوئے کہ کچھ کرنا ہی ہے تولڑکیوں سے بدکاری کرلو.کیاایسے موقع پر کوئی معقول آدمی یہ بات کہہ سکتاہے؟حضرت لوط ؑ کانبی کا مقام نظرانداز کردو.مگرایک معقول آدمی کے مقام سے تو ایک کافر بھی انہیں نہیں گرائے گا.پھر یہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ حضرت لوط ؑجوخداکے نبی تھے خودان لوگوں کو ایک اوربدکاری کی جو پہلی سے کم نہیں تعلیم دیتے ہیں کیاکوئی عقل مندآدمی بھی اس بات کوباورکرسکتاہے کہ عین اس وقت جب بدکاریوں کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آنے لگاتھا حضرت لوط ؑ ان کو ایک اوربدکاری کا مشورہ دیتے ہیں اوریہ بھول جاتے ہیں کہ
Page 345
ایسے ہی کاموں کی وجہ سے عذاب آرہاہے.آیت هٰؤُلَآءِبَنٰتِيْۤ کے متعلق عام لوگوں کے خیال کا رد حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے فقط یہ معنے ہیں کہ میری بیٹیاں تم میں بیاہی ہوئی ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں باہرسے آدمی تم کو نقصان پہنچانے کے لئے لایاہوں توتم میں میری بیٹیا ںموجود ہیں اگر میں کوئی شرارت کرو ں اور تم کو نقصان پہنچاکر یہاں سے بھاگ جائو ں توتم انہیں دکھ دے سکے ہو.آخر میں باپ ہوں ا س صورت کے ہوتے ہوئے میں تمہارے خلاف کس طرح کوئی قدم اٹھا سکتا ہوں؟ (دیکھو اس آیت کی مزید تشریح کے لئے سورۃ ہود ع ۷زیر آیت ۸۰)بعض کہتے ہیں کہ بَنٰتِیْ سے مراد حضرت لوط کے قول میں ان لوگوں کی بیویاں تھیں جو بوجہ نبی ہونے کے اوربڑی عمر والاہونے کے وہ ان کی بیویوں کو بیٹیاں کہتے ہیں (تفسیر کبیر امام رازی سورۃ حجر زیر آیت ھذا)اورکہتے ہیں اگر کچھ کرنا ہے تواپنی بیویوں سے جو چاہو کرو.یہ معنے اس غلط خیال سے اچھے ہیں مگران معنوں سے اس طرف ضرور اشارہ نکلتاہے کہ وہ لوگ ان مردوں سے بدکاری کرناچاہتے تھے اورمیں جیساکہ ثابت کرچکاہوں یہ قرآن کریم سے اورعقل سے ہرگز ثابت نہیں.پس یہ معنے گو نسبتاً اچھے ہیں لیکن قرآن کریم کے کامل مفہوم کوظاہرنہیں کرتے.اس جگہ ایک لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے.جو یہ ہے کہ اردو دان لوگ ا س آیت سے بہت دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ اوباشوں کی زبان میں فاعل کالفظ مباشر ت کرنے والے کے معنوں میں استعمال ہوتاہے.اورفاعلین کے لفظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب تو واضح ہے حالانکہ قرآن کریم عربی میں ہے نہ کہ اردو میں.عربی میں ایساکوئی محاورہ نہیں.دوسرے حضرت لوط ؑ تونبی تھے وہ اوباشوں کی زبان کیوں بولنے لگے.یہ مضمون کسی قدر رکیک ہے.مگرچونکہ مجھے اردودان طبقہ کو اس آیت کامضمون سمجھا نے میں مشکلات پیش آئی ہیں اوراس محاورہ کو انہیں پیش کرتے ہوئے دیکھاہے اس لئے میں نے باوجود حیاء کے اس کابھی رد کردیا ہے.آیت هٰؤُلَآءِ بَنٰتِيْۤ کا مطلب غرض اس آیت کے معنے صرف اتنے ہیں کہ حضر ت لوط نے اپنی بیاہی ہوئی بیٹیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے قبضہ میں ہیں پھر تم کو کیوں شک ہے.کہ میں تم سے غداری کروں گا.پس اگر تم آ ج ضرور میرے خلاف کسی اقدام پر تُلے ہوئے ہوتومیں تم کو ایک ایسی بات بتاتاہوں جو تمہاری تجویز سے (یعنے حضرت لوط ؑ کے مہمانوں کو ذلیل کرکے وہاں سے نکال دینے سے)بہت بہتر ہے اوراس میں مہمانوں کی تذلیل کا گناہ بھی نہیں ہوتا.اوروہ یہ کہ میری بیٹیو ں کی نگرانی رکھو اور اگر میں تم کو نقصان پہنچائو ں توان کوتکلیف دے کر تم مجھے دکھ دے سکتے ہو.اگریہ کہا جائے کہ لڑکیوں کو دکھ دینے کی تجویز ایک نبی کس طرح
Page 346
کرسکتاہے تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کی تسلی کے لئے تھا.ورنہ حضرت لوط جانتے تھے کہ نہ میں ان سے غداری کروں گا اورنہ لڑکیوںکو دکھ دینے کاسوال پیدا ہوگا.لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۰۰۷۳ (اے ہمارے نبی )تیری زندگی کی قسم (کہ)یہ (تیرے مخالفین بھی)یقیناً(انہی کی طرح )اپنی بدمستی میں بہک رہے ہیں.حلّ لُغَات.لَعَمْرُکَ.لَعَمْرُکَ اَلْعَمْرُ کے معنے ہیں.الحیاۃ ،زندگی.وَقِیْلَ الْعَمْرُدُوْنَ الْبَقَاءِ لِاَنَّہٗ اِسْمٌ لِمُدَّۃِ عِمارَۃِ الْبَدَنِ بِالْحَیَاۃِ وَالْبَقَاءُ ضِدُّ الْفَنَاءِ وَلِھٰذَا یُوْصَفُ الْبَارِیْ بِالْبَقَاءِ وَقَلَّمَا یُوْصَفُ بِالْعَمْرِ.بعض نے کہا ہے کہ عَمْرٌ کالفظ بَقَاءُکی نسبت کم زمانے کے لئے بولاجاتاہے کیونکہ عَمْرٌ اس عرصے کو کہتے ہیں جب تک کہ انسانی جسم میںز ندگی رہے اور بقاء کالفظ فناءکے مقابل پر استعمال ہوتاہے اسی اختلاف کی بناء پر خدا تعالیٰ کے لئے لفظ بقاء تواستعمال کیا جاتا ہے لیکن عمرٌ کااستعمال اللہ تعالیٰ کے لئے شاذ ہی ہوتاہے اَلْعَمْرُ اَیْضًا الدِّیْنُ.دین.وَمِنْہُ لَعَمْرِیْ فِی الْقَسَمِ اَیْ لَدِیْـنِیْ اور لَعَمْرِیْ کالفظ جو قسم کے طورپر استعمال ہوتاہے وہ انہی معنوں میں ہے یعنی مجھے اپنے دین کی قسم (اقرب)پس لَعَمْرُکَ کے معنی ہوں گے (۱) تیری زندگی کی قسم (۲)تیرے دین کی قسم.تفسیر.اللہ تعالیٰ کا مختلف اشیاء کی قسم کھانے کا مطلب بعض نے کہا ہے کہ زندگی کی قسم کھانادرست نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں قسم کھائی؟ (قرطبی زیر آیت ھذا).اس کاجوا ب یہ ہے کہ بے شک انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی بھی قسم کھانادرست نہیں.لیکن یہ تواللہ تعالیٰ کاقول ہے اوراللہ تعالیٰ نے تودن کی اور رات کی اورصبح کی اوردوپہر کی اورہوائوں کی بھی قسم قرآن میںکھا ئی ہے.پھر زندگی کی قسم اس کے لئے کس طرح معیوب ہوگئی ؟اصل بات یہ ہے کہ بند ہ جس کی قسم کھاتاہے اس کی عظمت کا اظہار کرتاہے اوراللہ تعالیٰ جہاں قسم کھاتاہے اس سے اس وجود کو جس کی قسم کھائی ہو بطور شہادت پیش کرنا مطلوب ہوتاہے.پس اللہ تعالیٰ کے لئے کسی شے کی قسم کھا نامعیو ب نہیں.اس قسم کا صرف یہ مطلب ہوتاہے کہ میں اس شے کو بطو ردلیل پیش کرتاہوں اوریہ قسم شہادت کی قسم ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی جاسکتی ہے کیونکہ اسی کو طاقت حاصل ہے کہ
Page 347
کائنات میں سے کسی جزوکو بطور شہادت کے پیش کرسکے کہ ہرشے اس کے اختیارمیں ہے.انسان میں کہاں طاقت ہے کہ وہ ایسا دعویٰ کرسکے.لَعَمْرُكَ میں آنحضرت ؐ کی عمر کی قسم کھائی گئی ہے دوسراسوال اس آیت کے بارہ میں یہ ہے کہ یہ قسم کس کی عمر کی کھائی گئی ہے.آیاحضرت لوط کی عمر کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی.بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لوط ؑ کی عمرکی قسم کھائی گئی ہے.اورملائکہ نے کھائی ہے (کشاف زیر آیت ھذا) اور حضرت ابن عباس کاقول ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ یہ قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی کھائی گئی ہے اوریہ فضیلت سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کوحاصل نہیں (ابن کثیر زیر آیت ھذا) اسی آیت کی تفسیر کے نیچے.میرے نزدیک قرآن کریم کی عبارت سے حضرت ابن عباس کے معنے زیادہ درست معلوم ہوتے ہیں کیونکہ کشاف کے معنوں کے رو سے ایک قالوا محذوف مانناپڑتا ہے اورمحذوف اسی جگہ نکالاجاتاہے جہاں سیاق وسباق دلالت کرتے ہوں اور دوسرے معنے نہ ہوسکتے ہوں.لیکن نہ تویہاں سیاق و سباق مجبور کرتے ہیں کہ اس قسم کو حضرت لوط کی نسبت مانا جائے اورنہ یہ ہی درست ہے کہ اس جگہ دوسرے معنے نہیں ہوسکتے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب واضح ہے اوراس پر کوئی اعتراض معناً یالفظاً نہیں ہوسکتا.پس یہی درست ہے کہ ا س جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرکی قسم کھائی گئی ہے یادوسرے لفظوں میں یہ کہ آپؐ کی عمر کے واقعات کواوپر کے واقعہ کے لئے بطور شہادت پیش کیاگیا.حضرت لوط ؑ کے ذکر کے بعد آنحضرت ؐ کی عمر کی قسم کھانے کا مطلب اصل بات یہ ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کا یہ قول بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ میری لڑکیاں تم میں موجود ہیں اگر میں تم سے کوئی دھوکہ کروں توتم ا ن کے ذریعہ سے مجھے سزادے سکتے ہو.تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ایک مشابہت بیا ن کی گئی تھی اوروہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تین بیٹیا ںکفار میں بیاہی ہوئی تھیں.آپ کے دعویٰ کی وجہ سے انہیں تکلیف دی گئی (السیرۃ النبویۃ لابن ہشام سعی قریش فی تطلیق بنات الرسول من ازواجھن).آنحضرت ؐ کی صاحبزادیوں کو حضرت لوط کی بیٹیوں سے مشابہت اللہ تعالیٰ نے اس مشابہت کی طرف اس واقعہ کو بیان کر کے اشار ہ کیا ہے اور بتایاہے کہ جس طرح حضرت لوط ؑ کی دوبیٹیاں کفار میں بیاہی ہوئی تھیں.وہی حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاہے.اور چونکہ اس مشابہت کے ذکر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کوصدمہ پہنچنا لازمی تھا.اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بے انتہا محبت کی وجہ سے جو اسے اپنے رسول سے تھی.آپؐ کے دل کو تسلی دی اورآپ سے ہمدردی کااظہار کیا.اورفرمایا کہ اے محمد!(صلی اللہ علیہ وسلم)اس واقعہ کومعلوم کرکے
Page 348
جو تیرے د ل کو صدمہ پہنچا ہے اسے ہم جانتے ہیں اوراس میں تجھ سے ہمدردی رکھتے ہیں.خصوصاًاس لئے کہ لوط کے مخالف باوجود اس قدر گند اہونے کے ان کی بیٹیوں کے ذریعے سے انہیں دکھ نہ دیتے تھے.جیساکہ سورئہ ہود میں ہے کہ جب حضرت لوط ؑ نے کہا کہ میری بیٹیا ںتم میں موجود ہیں اگر میں غداری کروں توتم ان کے ذریعہ سے مجھے دکھ دے سکتے ہو.اور چونکہ کوئی باپ اپنی بیٹیوں کادکھ برداشت نہیں کرسکتا.اس لئے سمجھ لوکہ کم سے کم ان کے خیال سے ہی میں تم کو دھوکہ نہ دوں گا.تواس پر ان لوگوں نے یہ جواب دیاکہلَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِی بَنَاتِکَ مِنْ حَقِّ (ہود :۸۰) تجھ کو معلوم ہے کہ تیری لڑکیوں کو دکھ دینے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہمارے لئے خطرہ توپیداکرے اوردکھ ہم تیری لڑکیوں کو دیں.یہ نہیں ہوسکتالیکن جہاں لوط کے دشمنوں کایہ حال تھا تیرے دشمن اپنی شرارت کے جوش میں اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ تجھ کو تیری لڑکیوں کے ذریعہ سے دکھ دیتے ہیں.یہ واقعہ اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوصاحبزادیا ںحضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ابولہب کے دوبیٹوں عتبہ اورعتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں (الاصابۃ فی تمییز الصحابۃ واسدالغابۃ ام کلثوم ) جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کادعوی کیاتواس ظالم نے اپنے لڑکوں کو عاق کرنے کی دھمکی دےکر انہیں طلاق دلوادی.آنحضرتؐ کی صاحبزادی حضرت زینب کو تکلیف دیئے جانے کا واقعہ اس طرح آپؐ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب ابوالعاص سے بیاہی ہوئی تھیں.جب وہ مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ جانے لگیں توظالموں نے ان کی سواری کو پیٹا اورانہیں سواری سے گرادیا.جس کے نتیجہ میں ان کاحمل ضائع ہوگیا.اوردیر تک بیمار رہیں (الاستیعاب فی معرفة الاصحاب کتاب النساء باب الزای ) سواللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تجھے تیری لڑکیوں کے ذریعہ سے دکھ دے چکے ہیں.اورپھر بھی دیں گے.(حضرت زینبؓ کاواقعہ بعد میں ہوا)ان لوگوں نے لوط ؑ کے دشمنوں جتنی بھی شرافت نہیں دکھا ئی مگر ہمیں تیری جان ہی کی قسم یہ اپنی شرارت میں اندھے ہورہے ہیں اوراس دعویٰ کی تائید میں ہم تیری زندگی کو بطورشہادت پیش کرتے ہیں.یعنے تونے ان کو کوئی دکھ نہیں دیا.بلکہ ہمیشہ ان کی خیر خواہی کی.مگریہ بلاوجہ اوربغیر قصور کے تجھے دکھ دیتے ہیں.پس یہی ثبوت ہے کہ یہ جوش مخالفت سے اندھے ہو رہے ہیں.اورہرگز خدا تعالیٰ کاتقویٰ ان کو حاصل نہیں.پس جب ان کی یہ حالت ہے کہ تجھ پر بلاوجہ اس قدر ظلم کررہے ہیں.توہم نے لوط کے دشمنوں کو جب اس سے کم جرم پر تباہ کیا.توکیا اس سے بڑے ظلم پر انہیں سزانہ دیں گے؟اس آیت کا تعلق سورۃ کے اصل مضمون سے یہ ہے.کہ یہ لوگ تجھ پرنازل ہونے والے کلام کومشتبہ کرنے کے لئے ایسی گندی حرکات کرتے ہیں.گویا اپنے خیا ل میں یہ سمجھتے ہیں.کہ تیری لڑکیوں کو دکھ دیاتوتیراجھوٹاہوناثابت
Page 349
ہوگیا.حالانکہ اصل میں انجا م دیکھا جاتاہے.ہم اپنے کلام کی عظمت دکھانے کے لئے اوراسے اعتراضوں سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک دن ان کو تباہ و برباد کردیں گے اورتیرابدلہ لے کر تیری عزت کوقائم کردیں گے.اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلّم اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَجِیْدٌ.فَدَتْ نَفْسِیْ وَرُوْحِیْ عَلَیْکَ یَامُحَمَّدُ قَدْاُوْذِیْتَ کَثِیْرًا فِی اَعْلَاءِ کَلِمَۃِ اللہِ رَفَعَ اللہُ شَأنَکَ وَاَحْیَا ذِکْرَ کِ اِلیٰ اَبَدِالْاَبادِ.فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَۙ۰۰۷۴ اس پر اس( موعود) عذاب نے دن چڑھتے (ہی)انہیں پکڑلیا.حلّ لُغَات.الصَّیْحَۃُ.الصَّیْحَۃُ اَلْعَذَابُ صیحۃٌ کے معنی عذاب کے ہیں.الْغَارَۃُ اِذَا فُوْجی ءَ الحیُّ بھَا(اقرب).ایسی غارت جو قبیلہ پر اچانک آجا ئے.مُشْرِقِیْنَ:مُشْرِقِیْنَ اَشْرَقَ سے اسم فاعل کاصیغہ مُشرِقٌ آتاہے اور مُشْرِقُوْنَ اس کی جمع ہے اور اَشْرَقَتِ الشَّمْسُ کے معنے ہیں طَلَعَتْ.سورج نکل آیا.اَضَاءَتْ سورج کی روشنی پھیل گئی.وَقِیْلَ شَرَقَتِ الشَّمْسُ طَلَعَتْ وَاَشْرَقَتِ الشَّمْسُ اَضَاءَتْ وَصَفَا شُعَاعُہَا.اورجب سورج کے لئے شَرقَتْ (ثلاثی مجرد)کہیں.تو اس کے معنے ہوں گے کہ سورج نکل آیا.اورجب اَشْرَقَتْ (ثلاثی مزید)استعمال کریں.تواس کے معنی ہوں گے کہ سورج کی روشنی خوب پھیل گئی.اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ.اَنَارَتْ بِاِشْرَاقِ الشَّمْسِ.سورج کے طلوع ہونے سے زمین پر روشنی پھیل گئی.اَشْرَقَ الرَّجُلُ.دَخَلَ فِیْ شُرُوْقِ الشَّمْسِ.اس پرطلو ع آفتاب کا وقت آگیا.(اقرب) تفسیر.پہلے مُصْبِحِیْنَ فرمایا اور اس آیت میں مُشْرِقِیْنَ پہلے مُصْبِحِیْنَ فرمایاتھا.اب یہاں مُشْرِقِیْنَ فرمایا ہے.بظاہر یہ اختلاف معلوم ہوتاہے.کیونکہ مُشْرِقٌ کے معنے ہیں جس پر سورج نکل آئے اورمُصْبِحٌ کے معنے بظاہر طلوع آفتاب کے وقت میں داخل ہونے والے کے ہیں.مُصْبِحِیْنَ اور مُشْرِقِیْنَ میں کوئی اختلاف نہیں لیکن حقیقتاً کوئی اختلاف نہیں کیونکہ صبح پوپھٹنے سے لے کر طلوع آفتا ب تک کوبھی کہتے ہیں.اوراول النہار یعنے دن کے پہلے حصہ کو بھی کہتے ہیں.پس دونوں لفظ درست ہیں.چونکہ سورج نکلتے وقت یہ واقعہ ہواتھا(پیدائش باب۱۹ آیت ۲۳) اس لئے مُصْبِحِیْنَ کہنا بھی درست ہے
Page 350
اورمشرقین کہنا بھی.فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ جس پر ہم نے اس (بستی )کی اوپر والی سطح کو اس کی نچلی سطح کردیااوران پر سنگریزوں سے بنے ہوئے پتھروں کی سِجِّيْلٍؕ۰۰۷۵ بار ش برسائی.حلّ لُغَات.اَمْطَرَ.اَمْطَرَ مَطَرَ سے ثلاثی مزید ہے.اور اَمْطَرَتِ السَّمَآءُ کے معنے ہیں.مَطَرَتْ أَیْ اَصَابَتْھُمْ بِالْمَطَرِ مینہ برسا وَ قِیْلَ مَطَر فِی الْخَیْرِ وَالرَّحْمۃِ وَاَمْطَرَفِی الشَّرِّ وَالْعَذَابِ اوربعض کہتے ہیں کہ مَطَرَ (ثلاثی مجرد)خیر اورحمت میں استعمال ہوتاہے اوراَمْطَرَ(ثلاثی مزید)شرّاورعذاب میں (اقرب) سِجِّیْل: سِجِّیْلٌ سَجَلَ سے ہے.اورسَجَل بِہٖ سَجْلًا کے معنے ہیں رَمیٰ بِہٖ مِنْ فَوْقَ.اس کو اوپر سے پھینکا.سَجَلَ الْمَآءَ:صَبَّہٗ پانی کو گرایا.اور السِّجِّیْلُ کے معنی ہیں حِجَارَۃٌ کَالْمَدَرِ سنگریزے.وَقِیْلَ مُعَرَّبَۃٌ اوربعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ معرّب ہے(اقرب)(یعنی غیر زبان کا ہے.لیکن جیساکہ رعد حل لغات آیت نمبر ۱۹ زیر لفظ جہنم اورابراہیم آیت نمبر۳۶ ز یرلفظ صنم بتایاگیاہے کہ جن الفاظ کا مادہ عربی میں استعمال ہوتاہے ان کو معرّب کہنا درست نہیں.پس یہ بھی معرّب نہیں) تفسیر.لوط ؑ کی قوم پر سخت عذاب آنے کی وجہ لوط ؑکی قوم نے چونکہ اعلیٰ اخلاق چھوڑکر ادنیٰ اخلاق اختیار کئے تھے.اس لئے خدا تعالیٰ نے بھی ان کے شہر کے اوپر کے حصہ کو نیچے کردیا اورکہاکہ جائو.پھر نیچے ہی رہو.بعض لوگ کہتے ہیں.پتھر کیونکر گرے.اس کا جواب یہ ہے.کہ شدید زلزلہ سے بعض دفعہ زمین کا ٹکڑا اوپر اٹھ کر پھر نیچے گرتاہے.ایسا ہی اس وقت ہوا.زمین جو پتھریلی تھی.اوپر اُٹھی اورپھر دھنس گئی اوراس طرح وہ پتھروں کے نیچے آگئے.یہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ ان کے گھروں کی دیواریں ان پر آپڑیں.معلوم ہوتاہے وہ لوگ پتھروں سے مکان بنایاکرتے تھے.سجیل کہتے بھی ہیں اس پتھر کو جوگارہ سے ملا ہواہو.پس یہ ایسی دیواروں پر خوب چسپاں ہوتا ہے جن میں پتھرگارہ سے لگائے گئے ہوں.
Page 351
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ۰۰۷۶ اس (ذکر) میں فراست سے کام لینے والوں کے لئے یقیناً کئی نشان (موجود )ہیں.حلّ لُغَات.متوسمین.مُتَوَسِّمِیْنَ تَوَسَّمَ سے اسم فاعل کاصیغہ مُتَوَسّمٌ آتاہے اورمُتَوَسِّمُوْنَ اس کی جمع ہے اورتَوَسَّمَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں تَخَیَّلَہٗ وَ تَفَرَّسَہٗ.اس پر غور کیا سوچ کر اس کی حقیقت کو معلوم کیا.طَلَبَ وَسْمَہُ.اَیْ عَلَامَتَہٗ.کسی چیز کی علامت دریافت کی.تَعَرَّ فَہٗ.کسی چیزکوپہچاننے کی کوشش کی.یُقَالُ تَوَسَّمْتُ فِیْہِ الْخَیْرَ.اَیْ تَبَیَّنْتُ فِیْہِ اَثْرَہٗ.جب تَوَسَّمْتُ فِیْہِ الْخَیْرَ.کامحاورہ استعمال کریں تومعنے یہ ہوں گے کہ میں نے خیر کے نشان اس میں پائے (اقرب)پس اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ کے معنے ہوں گے کہ اس میں غورکرنے والوں کے لئے کئی نشان ہیں.تفسیر.حضرت لوط ؑ کے واقعہ سے آنحضرت ؐ کے منکرین کو انتباہ یعنی جولوگ فراست سے کام لیتے ہیں ان کے لئے اس واقعہ میں نشانات ہیں.یعنے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوط کے واقعہ کو محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے مشابہت ہے.پس آپ کے دشمنوں کو بھی اسی طرح تباہ کیاجائے گا.جس طرح حضرت لوط کے دشمنوں کو تباہ کیاگیا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کوزلزلہ کا نشانہ تونہ بننا پڑا.مگر بدر کی جنگ میں ان پر پتھر پڑے یعنی آندھی چلی اورکنکر اُڑ اُڑ کرکفار کی آنکھو ں میں گھُس گئے.جن کی وجہ سے وہ نشانہ درست نہ لگاسکتے تھے.(دلائل النبوۃ للبیہقی باب التقاء الجمعین و نزول الملائکۃ وما ظھر فی رمی النبی بالقبضة) نیز معنوی طور پر بھی یہ سلوک ان سے ہوا.کہ بڑے چھوٹے کردیئے گئے اورچھوٹے بڑے.گویااوپر کاطبقہ نیچے آگیا اورنیچے کااوپر چنانچہ ابوجہل.عتبہ.شیبہ وغیر ہ اور ان کے خاندان تباہ ہوگئے.اورابوبکر ؓعمرؓ وغیرہ جوان سے چھوٹے سمجھے جاتے تھے بادشاہ بن گئے.حضرت عمرؓ کی خلافت میں اس قسم کا عجیب نظارہ نظرآتاہے.آپ حج کے لئے تشریف لے گئے.توعمائدین مکہ ملنے آئے.آپؓ نے غلام صحابہؓ کو صدر کے قریب جگہ دی اوران کو پیچھے بٹھایا.انہوں نے باہر نکل کر شکایت کی کہ آج ہمیں ذلیل کیا گیاہے.توخود ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے.جب ہمارے باپ دادے محمد رسول اللہ کی مخالفت کررہے تھے تویہ لو گ آپؐ پر ایمان لاکر قربانیاں کر ر ہے تھے.اب تویہی عز ت کے مستحق ہیں.(مناقب امیر المومنین عمر بن الخطاب ؓ از ابی الفرج
Page 352
عبد الرحمن بن علی بن محمد ابن الجوزی باب الثامن و الثلاثون فی ذکر عدلہ فی رعیتہ) وَ اِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ۰۰۷۷ اوروہ (کوئی گمنام جگہ نہیں بلکہ)ایک بڑے مستقل راستے پر (واقع )ہے.حلّ لُغَات.سبیل مقیم.سَبِیْلٌ مُقِیْمٌ اَیْ بَیِّنٌ وَاضِحٌ (تاج)یعنی واضح بیّن راستہ.تفسیر.یعنی ان کی بستیاں ایک ایسے راستہ پر واقع ہیں جو اب تک چلتاہے مٹانہیں.اس وجہ سے اے کفار! تمہارے قافلے شام کو آتے جاتے عین اس کے پاس سے گذرتے ہیں.پھر تم عبرت نہیں حاصل کرتے.حضرت لوط ؑ کی بستیاں عین اس راستہ پر واقع ہیں جو عرب سے شام کو جاتاہے.اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۰۰۷۸ اس (واقعہ )میں مومنوں (کے فائدہ)کے لئے یقیناً ایک نشان(موجود )ہے.تفسیر.آنحضرت ؐ کے زمانہ کے عذاب کو لوط ؑکے زمانہ کے عذاب سے مشابہت اس آیت میں مومنوں کے لئے اسے نشان قراردیاہے.جب کہ پہلی آیت کو متوسّمین کے لئے نشان قرار دیاتھا.یہ فرق اس لئے ہے کہ پہلی آیت میں یہ ذکر تھا.کہ اس واقعہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ سے مشابہت ہے چونکہ اس مشابہت کو ہرشخص نہیں معلوم کرسکتا.بلکہ خاص فراست والے معلو م کرسکتے ہیں.کیونکہ باریک مضمون ہے اس لئے متوسّمین کالفظ استعمال کیا.لیکن اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ و ہ بستیاں ایک چلتے ہوئے راستہ پر ہیں.اورایک تباہ شدہ بستی سے عبرت حاصل کرنا کوئی باریک مضمو ن نہیں بلکہ صرف دل کی خشیت سے تعلق رکھتاہے.یہ اس لئے فرمایا کہ اس سےمومن فائدہ اٹھاسکے.وَ اِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَۙ۰۰۷۹ اوراَیکہ والے (بھی)یقیناً ظالم تھے.حلّ لُغات.اَلْاَیْکَۃُ:اَلاَیْکَۃُ اَلاَیْکُ الشَّجَرُ الْکَثِیْرُ الْمُلْتَفُّ وَقِیْلَ الْغَیْضَۃُ تُنْبِتُ
Page 353
السِدْرَ وَالْاَرَاکَ وَنَحْوَھُمَا.اَلْوَاحِدُ اَیْکۃٌ.ایکۃ ایک کی مفرد ہے اوراس کے معنے گھنے درخت کے ہوتے ہیں اورنیز ایسے جنگل کے جس میں بیر ی اورپیلو کے درخت بکثرت ہوں.(اقرب) تفسیر.اصحاب الایکہ حضرت شعیبؑ کی قوم کا نام ہے اصحاب الایکہ حضرت شعیب کی قوم کادوسرانام ہے.ایکہ گھنے درخت کو بھی کہتے ہیں.اورایسے جنگل کو بھی جس میں بیری اورپیلو کے درخت بکثرت ہوں معلوم ہوتا ہے کہ مدین کے پاس کوئی گھنا جنگل تھا.جس میں ان دونوں قسموں کے درخت بکثرت پائے جاتے تھے.مدین کے باشندوں کو اصحاب الایکہ کہے جانے کی وجہ اس وجہ سے مدین کے باشندے اصحاب الایکہ کہلاتے تھے اورغالباً یہ نام عربوں نے رکھاتھا.جن کے قافلے مصر اورشام کو جاتے ہوئے مدین کے پاس سے گذرتے تھے اوراسی جنگل میں سے ان کا راستہ گزرتاتھا.اس لئے عربوں پر اتمام حجت کے لئے اسی نا م کو جو ان میں زیادہ معروف تھا استعمال کیا.حضرت شعیب کی قوم کے اصحاب الایکہ ہونے کا قرآن مجید سے ثبوت قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اصحاب ایکہ حضرت شعیب کی قوم تھی چنانچہ سورئہ شعراء میں فرماتا ہے کَذَّبَ اَصْحَابُ الْاَیْکَۃِ الْمُرْسَلِیْنَ اِذْقَالَ لَھُمْ شُعَیْبٌ اَلَا تَتَّقُوْن اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ (الشعراء :۱۷۷.۱۷۹) یعنے اصحاب ایکہ نے بھی رسولوں کاانکار کیا جبکہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم تقویٰ نہیں کرتے.میں تمہاری طر ف رسول ہوکر آیاہوں.اس آیت سے ثابت ہوتاہے کہ اصحاب الایکہ حضرت شعیب کی قوم تھی.لیکن دوسری جگہ حضرت شعیب کو مدین کی طرف رسول بتایا گیاہے.جیسا کہ فرمایا وَاِلیٰ مَدْیَنَ اَخَاھُمْ شُعَیْبًا (ہود :۸۵نیز الاعراف ۸۶و العنکبوت ۳۷) ہم نے مدین قوم کی طر ف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا تھا.اب سوال یہ ہے کہ کیا شعیب نام کے دونبی تھے یاحضرت شعیب دوقوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے مدین والوں کی طرف بھی اوراصحاب ایکہ کی طرف بھی ؟ مدین والے اور اصحاب الایکہ ایک ہی نسل کے دو حصے تھے میری تحقیق یہ ہے کہ ایک ہی نسل کے دوحصے تھے کچھ لوگوں کا گذارہ شہر ی تجارت پر تھا.اور کچھ لوگوں کادودھ گھی اون فروخت کرنے پر گذارہ تھا.اورایسے شہروں میں جو جنگل کے سروں پرہوتے ہیں یہ بات کثرت سے دیکھی جاتی ہے.مدین کے پاس جنگل کے ہونے کا ثبوت جغرافیہ سے یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ کیاواقع میں مدین کے پاس کوئی ایسا جنگل تھاجس میں بیری اورپیلو کے درخت پائے جاتے تھے.کیونکہ ایسی بات قیاس سے نہیں بتائی
Page 354
جاسکتی.اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں! جغرافیوں سے اس کا پتہ ملتا ہے.چنانچہ مولوی سلیمان صاحب ندوی اپنی کتاب ارض القرآن میںبرٹن کی کتاب بولڈمائنز آف مدین کے حوالہ سے لکھتے ہیں.کہ ایک یونانی جغرافیہ نویس لکھتاہے ’’خلیج عیلانہ(عقبہ)کے پیچھے جس کے چاروں طرف نبطی عرب رہتے ہیں.(ارض مدین یہ ہے)یوتیمانوس (بنوتیمن)کاملک ہے جو وسیع اورمسطح ہے.اورسیراب اورعمیق ہے.وہاں نباتات اوراشجار کے سوا کچھ نہیں ہوتا.جوتابقد آدم ہوتے ہیں.اورجن کی وجہ سے جنگلی اونٹ ہرنوں کے گلے اور بارہ سنگے رہتے ہیں.اورنیز مویشی اوربھیڑ کے گلے.مگر ان مواہب قسمت کے ساتھ شیر اوربھیڑیوں کاوجود بھی ہے.جن سے یہاں کے باشندوں کی خوش قسمتی مبدل بہ بدقسمتی ہے ‘‘(جلد ۲ صفحہ ۲۴).اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ مدین کے پاس (مدین خلیج عقبہ کے سر پر واقع ہے)ایک جنگل تھا جس میں (۱)قد آدم درخت تھے اورپیلو اورجنگلی بیر قدآدم ہی ہوتے ہیں.(۲)وہاں جنگلی اونٹ رہتے تھے.یہ بھی پیلو اوربیر کے درختوں کی تصدیق کرتاہے کیونکہ اونٹ اسی قسم کے درختوں پر گذران کرتے ہیں (۳)اس میں مواشی اوربھیڑوں کے گلے رہتے تھے.اس سے معلوم ہوتاہے کہ مدین کی قوم جانوربھی پالتی تھی اوراسی جنگل میں انہیں چرایاکرتے تھے.مدین قوم کا نام بھی تھا اور شہر بھی مدین نام اس شہر کا جو ایکہ کے سر پر تھا مدین قوم کی وجہ سے پڑاتھا.پس شہر کانام بھی مدین تھا اورقوم کانام بھی مدین تھا.چنانچہ قرآن کریم نے دونوں معنوں میں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے.قوم کے معنے میں سورئہ ہودمیں ہے.وہاں فرماتا ہےوَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا (ہود:۸۵نیز الاعراف :۸۶و العنکبوت :۳۷)اورشہر کے معنوں میں توبہ میں فرماتا ہے وَ اَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ (التوبۃ : ۷۰)یعنی کیا ان کو مدین شہرکے رہنے والوں اوران بستیوں کی خبر نہیں پہنچی جن کو اُلٹادیاگیاتھا (یعنی قوم لوط کی بستیاں) مدین قوم حضرت ابراہیم ؑ کی نسل سے تھی یہ مدین قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی بائبل میں لکھاہے.’’اورابراہیم نے ایک اورجوروکی.جس کانام قتورہ تھا.اوراس سے زمران اوریقسان اورمدان اورمدیان اوراسباق اورسوخ پیداہوئے.اوریقسا ن سے صباء اوردوان پیداہوئے.اوردوان کے فرزندا سوری اورلطوسی اور لومی تھے.اورمدیان کے فرزند عیفہ اورغفر اورحنو ک اورابیداع اور الدوعاتھے.اوریہ سب بنو قتورہ تھے.(پیدائش باب ۲۵ آیت اتا۴) اس حوالہ سے معلو م ہوتاہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے.اوران کی بیوی قتورہ کے پیٹ سے پیداہوئے تھے.چونکہ اس جگہ صرف یقسان اورمدیان کی اولاد گنائی گئی ہے.معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لڑکوں
Page 355
کی اولاد نہیں ہو ئی یا ان کی اولاد زیاد ہ نہیں پھیلی اور بھائیوں کی اولاد کے ساتھ مل جل گئی.یقسان جو بڑے لڑکے تھے ان کی نسل میں سے ان کے لڑکے دوان کی نسل بھی ایک قبیلہ کی صورت میں مشہو رہے.اوریہ لوگ مدین یعنی چچا کی اولاد کے ساتھ ساتھ رہاکرتے تھے.چنانچہ مصنف ارض القرآن کاخیال ہے.کہ اصحاب الایکہ دوان قو م ہی کے لوگ تھے جو مدین کے ساتھ ہی ایکہ میں رہتے تھے (جلد ۲ صفحہ ۲۱،۲۲).اورگویا بمنزلہ ایک ہی قوم کے تھے میرے نزدیک یہ رائے معقو ل ہے.بشرطیکہ یہ سمجھا جائے کہ دونوں قومیں مل کررہتی تھیں.اوران کا ایک ہی قسم کاتمدن تھا.تجارت پیشہ بھی تھے اورجانوروں کے گلے بھی پالتے تھے.یہ نہیں کہ ایک حصہ تجارت پیشہ تھا.جومدین تھے اورایک حصہ جانو ر پالنے والا تھا.جو دوان تھے اورجنگل میں رہتے تھے.کیونکہ یہ قرآن کریم کے بیان کے خلاف ہے.بہرحال اصل قوم بنو قتورہ تھی.جوایک ماں اورباپ سے تھے.باقی تواندرونی تقسیمیں تھیں.بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر یہ قوم بنو اسماعیل کے اندر جذب ہوگئی تھی کیونکہ پیدائش باب ۳۷.آیت ۳۶ میں پہلے تو لکھا ہے کہ حضرت یو سف کو مدیانیوں نے فوطیمار کے پا س مصر میں فروخت کردیا.اورپھر باب ۳۹ میں لکھا ہے کہ فوطیفار مصری نے یوسف کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے خریدا (آیت ۱).اس سے معلو م ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے یہ قوم بنو اسماعیل میں جذب ہوگئی تھی.اور وہی قوم کبھی مدیانی کہلاتی تھی.اور کبھی اسماعیلی.مدین قوم کا زمانہ باقی رہے یہ سوال کہ یہ قوم کب ہوئی.اورشعیب کون تھے؟ان سوالات کے جواب مفسرین اورمؤرخین نے مختلف دیئے ہیں ان کے لئے دیکھو سورہ اعراف ع ۱۸؍۱۱.اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ کے ایک ہونے کا ثبوت قرآن سے یہ امر کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی جماعت یاقوم تھے.اس امر سے بھی ثابت ہوتاہے کہ قرآن کریم نے ان دونوں کے عیوب ایک ہی قسم کے گنائے ہیں.سورئہ اعراف میں مدین قوم کی نسبت آتاہے.فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا(الاعراف :۸۶)ماپ اورتول پورے دیاکرو اورلوگوں کو چیزیں تول کر دیتے وقت کمی نہ کیا کرو.اورزمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو.بعینہٖ یہی الفاظ اصحاب ایکہ کی نسبت ہیں.جن کا ذکر سورہ شعراء میں آتاہے انہیں مخاطب کرکے بھی حضرت شعیب فرماتے ہیںاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ.وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ.وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (الشعراء :۱۸۲.۱۸۴) یعنی وزن پورادیا کرو.اورلوگوں کو گھاٹانہ دیا کرو.اورسیدھی ڈنڈی سے تولا کر واورلوگوں کی
Page 356
چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو.اورزمین میں فساد نہ کیا کر و.ان دونوں حوالوں سے ظاہر ہے کہ اصحاب مدین یااصحاب ایکہ میں ایک ہی قسم کی بدیاں تھیں اوران کا بڑا گذارہ تجارت پر تھا اوراس میں وہ دھوکے فریب سے بہت کام لیتے تھے.اگریہ سمجھا جائے کہ مدین شہر میں تومدین قوم رہتی تھی.اوردوان جنگل میں رہتے تھے تویہ بھی ماننا پڑے گاکہ مدین قوم کاگذارہ تجارت پر تھا.اوراصحاب ایکہ کا گلہ پالنے پر.تواس صورت میں قرآن کریم نےجواصحاب ایکہ کے کام بھی تجارت میں دھوکہ دینا اور باٹو ں اورپیمانوں میں شرار ت کرنا بتایا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے.پس اصل بات یہ ہے کہ دونوں نام ایک ہی قوم اورایک ہی تمدن رکھنے والی قوم کے ہیں.صرف دوصفات کی وجہ سے دوناموں سے بنو قتورہ کو پکاراگیاہے.فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ١ۘ وَ اِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍؕؒ۰۰۸۰ اس لئے ہم نے انہیں (بھی اسی طرح سخت )سزادی تھی.اوریہ دونوں (جگہیں )ایک (صاف اور)واضح راستے پر (واقع )ہیں.حلّ لُغَات.امام مبین لَبِاِمَامٍ مُّبِین:اَلْاِمَامُ الطَّرِیْقُ الْوَاسِعُ.امام کے معنے کھلے راستہ کے ہیں وَبِہِ فُسِّرَ قَوْلُہُ تَعَالیٰ وَانَّھُمَالَبِاِمَامٍ مُّبِیْنٍ اَیْ بِطَرِیْقٍ یُؤَمُّ اَیْ یُقْصَدُ:یعنے آیت انَّہُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِینٍ میں امام کے معنے کھلے راستہ کے کئے جاتے ہیں یعنی ایسا راستہ جس کاقصد کیا جاتا ہے وَقَالَ فَرَّاء اَیْ فِی طَرِیْقٍ لَھُمْ یَمُرُّوْنَ عَلَیْھَا فِی اَسْفَارِھِمْ فَجَعَلَ الطَّرِیْقَ اِمَامًا لِاَنَّہُ یُتَّبَعَ اورفرّاء نے اِمَامٍ مَّبِیْنٍ کے معنے کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ راستہ جس پر وہ اکثر اپنے سفروں میں گذرتے ہیں اورراستے کوامام اس لئے کہا کہ اس کے پیچھے چلاجاتاہے یعنی جدھر وہ جاتا ہے ادھر ہی جانا پڑتا ہے (تاج) تفسیر.اصحاب الایکہ اصحاب مدین کے مقام کا محل و قوع اصحاب ایکہ یا اصحاب مدین کا مقام ایسا تھا کہ شام اورمصر کوجانے والے قافلے ان کے پاس سے گذرتے تھے.اورمبین اس لئے فرمایا.کہ وہ راستہ بہت چلتاتھا.اورجوراستے بہت چلتے ہوں ان کے نشان واضح ہوتے ہیں.اس قوم کے ذکر سے اس امر کی ایک اورمثال پیش کی ہے کہ استراق سمع کرنے والے لوگ آخر تباہ کردیئے جاتے ہیں.قوم لوط کے متعلق سبیل مقیم اور اصحاب الایکہ کے متعلق امام مبین کہنے کا مطلب قوم لوط کے
Page 357
متعلق فرمایاتھا.وہ ایک سَبِیْلٍ مُّقِیْمٍ پرواقع ہیں.اوراس جگہ فرمایا ہے اصحا ب ایکہ کا مقام ایک اِمَامٍ مُّبِیْنٍ پر واقع ہے.اس میں یہ اشارہ ہے کہ لوط کی بستیوں کے پاس سے گذرنے والا راستہ ہمیشہ قائم رہے گا لیکن ایکہ والے راستہ کے نشانات توباقی رہیں گے.لیکن اس راستہ پر قافلوں کاگذر بند ہوجائے گا.چنانچہ واقعات نے اس کی تصدیق کردی.پہلا راستہ تو اب تک جاری ہے دوسرے پر قافلے جانے بند ہوچکے ہیں.وَ لَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَۙ۰۰۸۱ حجروالوں نے (بھی )یقینا(ہمارے)پیغمبروں کو جھٹلایاتھا.حلّ لُغَات.الْحِجر:الْحِــجْرُ اَلْحِصْنُ حجرکے معنے ہیں.قلعہ.نیزدیار ثمود کوبھی حجر کہتے ہیں (اقرب) الحِجْرُ وَالتَّحْجِیْرُ اَنْ یُجْعَلَ حَوْلَ الْمَکَانِ حِجَارَۃٌ.حجر اورتحجیر کے معنے مکان اوراردگرد پتھروں کی دیوار بنانے کے ہیں.وَسُمِّیَ مَااُحِیْطَ بِہِ الْحِجَارَۃُ حِـجْرًا.اورجس جگہ کے گرد پتھر وں کی دیوار ہو اسے بھی حجر کہتے ہیں.(مفردات) تفسیر.یہ رکوع اوراگلی سورۃ النحل کاپہلارکوع بہت سے اہم مطالب اورپیشگوئیوں پر مشتمل ہیں.اصحاب الحجر سے مراد حجر سے مراد وہ احاطہ یاقلعہ یا شہرہوتاہے جس کے گرد پتھروں کی دیوار ہو.اصحاب الحجر سے مراد ثمود و قوم صالح کاشہرہے.اسے حجر اس لئے کہتے تھے کہ مضبوط فصیلوں کاشہر تھا.اورجیسا کہ اگلی آیات سے ظاہر ہے پتھروں سے اس کی تعمیر میں بہت کام لیا گیاتھا.آنحضرت ؐ کا غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے حجر کے مقام سے گزرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے ا س مقام کے پاس سے گذرے تھے.آپ نے صحابہ کو وہاں کاپانی استعمال کرنے سے منع فرمایاکہ یہ بستی الٰہی عذاب کا مقام ہے(بخاری کتاب الانبیاء باب قولہ تعالی وکذب اصحاب الحجر ) ایک رسول کے انکار سے سب رسولوں کا انکار آیت زیر تفسیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب الحجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا.حالانکہ انہوں نے صرف حضرت صالح کاانکارکیا تھا.اس طرز کلام کو سورئہ شعراء میں بھی استعمال کیاگیا ہے.وہاں فرماتا ہے کہ نوح ؑ کی قوم نے رسولوں کاانکار کیا (الشعراء:۱۰۶) قوم عاد نے رسولوں کاانکار کیا (الشعراء:۱۲۴)قوم ثمود نے رسولوں کاانکار کیا (الشعراء:۱۴۲)قوم لوط نے رسولوں کاانکار کیا (الشعراء:۱۶۱)
Page 358
حالانکہ ان سب مقامات پر صرف ایک رسول کے انکار کا ذکر ہے اور حضرت نوح ؑ سے پہلے توکوئی بہت سے رسول گزرے بھی نہ تھے کہ ان کے انکار کا ذکر ہوتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح ؑ اول الرسل تھے.(بخاری کتاب الانبیاء باب قولہ تعالیٰ ولقد ارسلنا اِلی قَوْمِہٖ) ایک رسول کے انکار سے سب رسولوں کے انکار کا الزام لگائے جانے کی وجہ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک رسول کے انکار پر کیوں سب رسولوں کے انکار کا الزام لگاگیاہے؟اس کے متعلق علامہ ابو حیا ن مصنف تفسیر بحر محیط نے نہایت لطیف بحث کی ہے.وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کہاگیا ہے کہ ایک رسول کے انکارکرنے والوں نے گویا سارے رسولوں کا انکار کیا (البحر المحیط زیر آیت ھذا).اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان وہی نفع دیتاہے جوسمجھ کر لایا گیاہو.پس جو شخص کسی ایک رسو ل کو پہچان کر اورسمجھ کر مانے گا وہ سب کو مان لے گا(جیسے وہ شخص جس نے خربوزہ یاآم کھایاہو وہ جب کبھی خربوزہ یاآم دیکھے گافورًا پہچا ن لے گاکہ یہ خربوزہ یاآم ہے ایسا ہی جس شخص نے ایک نبی کو سمجھ کر مان لیاوہ یقیناًدوسرے نبیوں کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس نہ کرے گا)مگر جس نے کسی ایک رسول کابھی انکار کیا.اس کے متعلق ہم نتیجہ نکال لیں گے کہ وہ خواہ کسی رسول کے وقت میں ہوتا ا س کابھی انکار کرتا.کیونکہ سب نبیوں کے حالات ایک سے ہوتے ہیں.یہ نکتہ نہایت لطیف ہے اورزبردست سچائی پر مشتمل ہے اوروہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں قوم نے اگر فلاں مدعی کاانکار کیا ہے.توکیاہوا؟وہ پہلے بہت سے رسولو ں کو مان رہے ہیں.کیاان پر ایمان لانا انہیں نفع نہ دے گا؟وہ حقیقت ایمان سے ناواقف ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کا پہلے نبیوں پر ایمان محض رسمی ہوتاہے.اگر وہ سمجھ کرپہلے رسولو ںکو مان رہے ہوں توجو شخص انہی کے نقش قدم پر آیاہو اورانہی کے حالات میں سے گزررہاہوا س کا انکار کیوں کریں؟پس ان کاماننا ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ رسمًااورعادتًاہے اورایسے ایمان کو ایمان کہنا ظلم صریح ہے.وَ اٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَۙ۰۰۸۲ اورانہیں(بھی)ہم نے اپنے (ہرقسم کے)نشان دیئے تھے جس کا نتیجہ( اُلٹا )یہ ہواکہ وہ ان سے روگردان ہوگئے تھے.حلّ لُغَات.مُعْرِضِیْنَ:مُعْرِضِیْنَ اَعْرَضَ سے اسم فاعل مُعْرِضٌ بنتاہے اورمُعْرِضُوْنَ اس کی جمع ہے.اَعْرَضَ کے معنے ایک طرف ہونے کے ہیں.کیونکہ اَعْرَضَ عَرَضَ سے نکلاہے جس کے معنی پہلو کے
Page 359
ہیں.پس اعراض کے معنے پہلو تہی کے ہوئے.یہ دستورہے کہ جس سے اعراض مقصود ہو انسان اس سے منہ پھیر لیتا ہے اوریہ ناراضگی کی علامت ہوتی ہے پس مُعْرِضِیْن کے معنے ہوئے کہ انہوںنے اس سے انکارکیا.انہوں نے منہ پھیر لیا اورتوجہ نہ کی.(المفردات) تفسیر.یعنے انہیں آیات الٰہی دکھائی گئیں.مگر انہوں نے اعراض کیا.پس کیونکرمانا جائے.کہ ویسی ہی آیات دیکھ کر دوسرے نبیوں کووہ مان رہے ہیں یامان سکتے ہیں.گزشتہ تین آیات میں تین قوموں کا ذکر گزشتہ آیات میں تین قوموں کا ذکرکیا گیا ہے.قوم لوط.قوم شعیب اورقوم صالح.ان میں سے قوم صالح پہلے تھی.پھر قوم لوط.پھرقوم شعیب.قوم لوط، شعیب ،صالح کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ان کے زمانے کی ترتیب کو بدلنے کی وجہ اب سوال یہ ہے کہ زمانہ کی ترتیب کوکیوں بدلاگیا ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ مکہ والوں کو یہ بتانا مقصودہے کہ پہلے انبیاء جن کو تم جانتے ہو.ان پر نازل ہونے والے کلام کے منکر بھی ایک حد تک شرارتیںکرنے کے بعد ہلاک کردیئے گئے تھے.محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکارپر تم خوش نہ ہو.اوریہ نہ خیال کرو کہ ہم غالب ہیں.اور اب تک ہماری شرارتوں کی سزانہیں ملی اپنے وقت پر تم کو بھی سزا ملے گی جس طرح ان کو ملی اس حجت کو پیش کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہوسکتاتھا کہ زمانہ کے لحاظ سے واقعات کو پیش کیا جاتا.لیکن دوسراطریق یہ بھی ہوسکتاتھا.کہ اس فاصلہ کے لحاظ سے ان کا ذکر کیاجاتا جس پر یہ قومیں عربوں سے دور یا نزدیک واقع تھیں.اوراس موقع پر یہی طریق اختیار کیا گیا ہے اورپہلے زیادہ دور فاصلہ والی قوم یعنی قوم لوط کا ذکر کیاگیا ہے پھر کہا گیاہے کہ لو ان سے بھی قریب تر ایک قوم گزری ہے.یعنی قوم شعیب.ان کابھی حال سن لو پھر اس کے بعد ثمود کی تباہی کابیا ن کیا.کہ لو یہ قوم قوم شعیب سے بھی تمہارے قریب تر ہے.اورخود عرب کے علاقہ میں واقع ہے.ان کے حالات سے ہی عبرت حاصل کرو.ا س سورۃ میں ان قوموں کا ذکر کیاگیاہے جن میں تحریر کارواج کم تھا.اورجن کو عرب مانتے تھے.حضرت آدم تو سب کے ساجھے ہیں.حضرت لوط حضرت ابراہیم کے رشتہ دارتھے.اوراس طرح عربوں کے اجداد میں سے تھے.حضرت شعیب مدین میں سے تھے جوبنو اسماعیل کے بنو العَم تھے.اوربنواسماعیل سے گہراتعلق رکھتے تھے اور انہی میں جذب ہوگئے تھے.ثمو د خالص عرب تھے.(مروج الذھب للمسعودی الجزء الثانی ذکر مکة و أخبارھا)
Page 360
وَ كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ۰۰۸۳ اوروہ پہاڑوں کے بعض حصوں کوکاٹ کر امن سے مکان بناتے تھے.حلّ لُغَات.یَنْحِتُوْنَ.یَنْحِتُوْنَ نَحَتَ سے مضارع جمع غائب کاصیغہ ہے اورنَحَتَ الْحِجَرَ کے معنے ہیں.سَوَّاہُ وَاَصْلَحَہٗ.پتھر کو کاٹ کر درست کیا اورٹھیک کیا.وَفِی الْقُرْآنِ تَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا اَیْ تَتَّخِذُوْنَ.اورقرآن مجید میں جو آیت يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ آئی ہے.اس کے معنی یہ ہیں کہ تم پہاڑوں میں گھر بناتے ہواورنحتَ الجبل کے معنے ہیں حَفَرَہٗ اس کو کھودا.(اقرب) البیت.اَلْبُیُوْتُ اس کامفرد اَلْبَیْتُ ہے جس کے معنے ہیں.اَلْمَسْکَنُ سَوَاءٌ کَانَ مِنْ شَعْرِ اَوْمَدَرٍ یعنی بیت مسکن کو کہتے ہیں خواہ وہ بالوں سے یعنی اون کابنا ہواہو جیسے خیمے وغیرہ ہوتے ہیں.یاکچی مٹی گارے وغیرہ کابناہواہو.یعنی کچاو پکا مکان.اَلشَّرَفُ اور بَیْتُ شَرَفٍ یعنی بلندی اورعزت کو بھی کہتے ہیں.الشَّرِیْفُ اورشریف یعنی سردار قوم کو بھی بیت کہتے ہیں کیونکہ قو م اس کے سایہ تلے رہتی ہے اوروہ قو م کے لئے بطور حفاظت کے ہوتاہے (اقرب) سردار قوم کو بیت کہے جانے کے متعلق چند لطیف اشعار اس محاورہ کے استعمال کے متعلق چند نہایت لطیف اشعار ایک مجذوب کے میں نے تاریخ میں پڑھے ہیں کہتے ہیں.حضرت جنید بغداد ی فوت ہوئے تو ایک مجذوب جو بغداد کے شہر میں رہتاتھا.ان کے جناز ہ کے موقعہ پر دیکھا گیا اس نے بلند آواز سے ان کی نعش کی طرف اشارہ کرکے یہ شعرپڑھے وَاأَسْفَاعَلیٰ فِرَاقِ قَوْمٍ ھُمُ الْمَصَابِیْحُ وَالْحُصُوْنُ وَالْمُدُنَ وَالْمُزْنُ وَالرَّوَاسِیْ وَالْخَیْرُ وَالْاَمْنُ وَالسُّکُوْنُ لَمْ تَتَغَیَّرْ لَنَا اللَّیَالِیْ حَتّٰی تَوَفّٰھُمْ الْمَنُوْنُ فَکُلُّ جَمْرٍلَنَا قُلُوْبٌ وَکُلُّ مَائٍ لَنَا عُیُوْنُ (تاریخ بغداد لامام ابی بکر حمد بن علی البغدادی جلد ۷ ص ۲۵۶ ) یعنے ہائے افسوس ان لوگوں کی جدائی پر روشن چراغ تھے اورقلعے تھے اورشہر تھے اوربادل تھے اورپہاڑ تھے اور امن تھے اورسکون تھے ہمارے لئے.زمانہ اس وقت تک نہیں بدلا جب تک موت نے ان کو وفات نہیں دی.
Page 361
مگراب تویہ حال ہے کہ دل انگارا ہے توآنکھیں پانی بہا رہی ہیں.ا س آگ کے سوا ہمارے پاس کوئی آگ نہیں.اوراس پانی کے سواکوئی پانی نہیں.ان اشعار میں نہایت لطیف طور پر بتایاگیاہے کہ روحا نی سردار قلعو ں اور شہروںاو ربادلوں اورپہاڑوںکی حیثیت رکھتے ہیں اوردنیا گویا ان میں بستی ہے اور ان کے ذریعہ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے.تفسیر.اصحاب الحجر متمدن اور متمول قوم تھی اس آیت میں بتایاگیاہے کہ وہ لو گ پہاڑوں کو کھود کھود کرمکانات بنایاکرتے تھے اوربڑے طاقتور تھے کو ئی ان پر حملہ کی جرأت نہ کرسکتاتھا.اس سے معلوم ہوتاہے کہ وہ قوم بڑی متمدن اورمتمول تھی کہ کوئی قوم ان کامقابلہ نہ کرسکتی تھی.کیونکہ یہ قوم دونوں علاقوں خشکی اورپہاڑی علاقوں میں رہتی تھی.اٰمِنینَ کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ قوم ایسی طاقتور تھی کہ کچھ حصہ سال کا پہاڑوں پر سیر و تفریح کے لئے گزارتی تھی.مگر باوجود اس کے کسی کو ان کے ملک پر حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوتی اوران کے پیچھے ملک میں امن رہتا تھا.یا یہ کہ وہ امن کی حالت میں پہا ڑ پر جاتے تھے.کسی گھبراہٹ اورڈرکی وجہ سے اوردشمن سے پناہ لینے کی غرض سے نہیں.اصحاب الحجر کے پہاڑوں کو کھودنے سے مراد پہاڑ کھو د کر مکان بنانے کایہ مطلب نہیں کہ اس کے سوااورقسم کے ان کے مکان نہ ہوتے تھے بلکہ اس سے خاص عمارتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے ان کے تمدن کی ترقی ظاہرہوتی ہے.معلوم ہوتا ہے کہ فن تعمیر میں ان کو خاص مہارت تھی اور انہوں نے بعض اپنی قو می عمارات پہاڑ کھود کربنائی تھیں جیسے الیفنٹاکیوز بمبئی میں ہیں وہ بھی پہاڑ کھو دکر بنائی گئی ہیں اورہندوفن تعمیر کی مشہو ریاد گار ہیں باہرسے آنے والے سیاح ان کو دیکھنے جاتے ہیں.اسی قسم کی بعض عمارتیں فن تعمیر کے اظہار کے لئے معلوم ہوتاہے اس قوم نے بھی بنائی تھیں.فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَۙ۰۰۸۴ پھر(وعید کے مطابق)صبح ہوتے (ہی)اس (موعود)عذاب نے انہیں پکڑ لیا.حلّ لُغَات.مُصْبِحِینَ :مُصْبِحِیْنَ اَصْبَحَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں دخَلَ فِی الصَّبَاحِ وہ صبح میں داخل ہوایعنی اس پر صبح کا وقت آیا.فَاَخَذَتْھُمُ الصَّیْحَۃُ مُصْبِحِیْنَ اَیْ وَھُمْ دَاخِلُوْنَ فی الصَّبَاحِ یعنی ان کو
Page 362
زلزلہ نے صبح ہوتے ہی آپکڑا.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے انہیں صبح کے وقت عذاب نے آدبایا.دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عذاب زلزلہ کاتھا جیسے کہ سورئہ اعراف میں بیان فرمایا ہے فَاَخَذَتْھُمُ الرَّجْفَۃُ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دَارِھِمْ جَاثِمِیْنَ (الاعراف:۷۹) ان کے انکا رکی وجہ سے انہیں زلزلہ نے آپکڑا.نتیجہ یہ ہواکہ وہ اپنے گھرو ںمیں زمین پر گر ے کے گرے رہ گئے.یعنی مکانوںکے ملبہ کے نیچے دب گئے.اورکوئی ایسا بھی نہ رہا جو ان کی لاشوں کو اند ر سے نکالتا.فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَؕ۰۰۸۵ اورجو(مال) وہ جمع کیا کرتے تھے اس نے انہیں (اس وقت کچھ بھی)فائدہ نہ دیا.حلّ لُغَا ت.اَغْنٰی عَنْہُ :تشریح کے لئے دیکھو حل لغات سورئہ ابراہیم آیت نمبر ۲۲ جلد ھذا.یَکْسِبُونَ:یکسبون کَسَبَ سے مضارع جمع غائب کاصیغہ ہے.تفصیل کے لئے دیکھو سورہ رعد آیت نمبر۴۳ جلد ھذا.تفسیر.اصحاب الحجر کے اپنے بنائے ہوئے سامانوں سے تباہ کئے جانے کے ذکر کا مطلب یعنے وہ توبڑے بڑے مکان اپنی حفاظت کے لئے بناتے تھے مگر ان کی یہ صفت ان کے لئے اس وقت الٹی پڑی.کیونکہ جتنے بڑے مکان ہوں اتنا ہی زیادہ وہ زلزلہ میں نقصان پہنچاتے ہیں.کیونکہ ان کے نیچے دب جانے والے انسان کی نجات کی کوئی امید نہیں رہتی.اس میں اس طرف اشار ہ کیاہے کہ اے اہل مکہ تم سامان سامان کا شورمچارہے ہو.یاد رکھو کہ جب ہماراعذاب آتاہے تومعذب قوم کے سامان ان کو فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ ان کی ہلاکت کو اورزیادہ خطرناک بنادیتے ہیں.وَ مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَاۤ اِلَّا بِالْحَقِّ١ؕ اورہم نے آسمانوں اورزمین کو حق(و حکمت) کے ساتھ ہی پیدا کیاہے وَ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ۰۰۸۶ ا وروہ (موعودہ)گھڑی یقیناً آنے والی ہے اس لئے تو(ان کی زیادتیوں پر )مناسب درگذر سے کام لے.حل لغات.بِالحقّ.الحقّ کے لئے دیکھو سورہ رعد آیت نمبر ۱۵ جلد ھذا.
Page 363
اصفح.اصْفَحْ صَفَحَ سے امرکاصیغہ ہے اورصَفَحَ عَنْہُ صَفْحًا کے معنے ہیں اَعْرَضَ عَنْہُ وَتَرَکَہٗ وَحَقِیْقَتُہٗ وَلَّا ہُ صَفْحَۃَ وَجْھِہِ.ا س سے اعراض کیا اوراس کو چھوڑ دیا.اورصَفَحَ کے اصل معنے یہ ہیں.کہ اس سے اپنے منہ کو ایک طرف کر لیا.یعنی اس کی طرف توجہ نہ کی.صَدَّعَنْہُ اس سے رک گیا.اَعْرَضَ عَنْ ذَنْبِہٖ اس کے گناہوں سے درگذر کیا اور اسے معاف کیا.صَفَحَ النَّاسَ.نَظَرَ فی اَحْوَالِھِمْ.لوگوں کے حالا ت کو بغوردیکھا.صَفَحَ فِی الْاَمْرِ نَظَرَفِیْہِ.کسی معاملہ میں غورو فکر کیا.اَلصَّفْحُ.صَفَحَ کامصدر ہے نیز اس کے معنے ہیں اَلْجَانِبُ.طرف.صَفْحٌ من الْاِنْسَانِ.جَنْبُہُ انسان کاپہلو.(اقرب) پس فَاصْفَحِ الصَّفْحَ کے معنے یہ ہوئے کہ (۱)ان سے منہ پھیر لے.یعنی اب اتمام حجت ہوچکی ہے اس لئے اب منکروں سے بحث و مباحثہ بند کردو (۲)ان لوگوں سے زیادہ تعلق نہ رکھو.(۳)ان کے گناہوں سے اعراض کرو.یہ معنے یہاں مراد نہیں (۴)ان کی حالت پر اچھی طرح غور کرو.اورحالات کا بغورمطالعہ کرو.اوردیکھو کہ کیاسے کیا ہورہا ہے ؟(۵)ان کے اموراورحالات کی طرف دیکھو کہ کس طرح گمراہی کی طرف جارہے ہیں.الجمیل:اَلْجَمِیْلُ جَمُلَ سے صفت مشبّہ ہے اورجَمُلَ الرَّجُلُ.یَجْمُلُ جَمَالًاکے معنے ہیں.حَسُنَ خَلْقًا وخُلْقًا کہ ظاہر و باطن کے لحاظ سے اچھا ہوگیا (اقرب) پس فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الجَمِیْلُ کے معنے ہوں گے کہ ایسادرگذر کرو جو ہررنگ میں اچھا ہو.تفسیر.لفظ ساعۃ اور اس کا استعمال یعنے آسمان و زمین کی پیدائش پر غورتوکرو کیا وہ بلا مقصد نظر آتی ہے اس کارخانہ پر نظر ڈالنے سے ہراک عقل مند سمجھ سکتاہے کہ اس قدر بڑا نظام کس غرض سے ہے.اوراس سے نتیجہ نکا ل سکتاہے کہ ساعۃ ضرور آنے والی ہے.اورساعۃ کالفظ قیامت کے لئے بھی استعمال ہوتاہے.اوراس موعود گھڑی کے لئے بھی جو انبیاء کے دشمنوں کی تباہی اوران کے ماننے والوں کی ترقی کے لئے مقررہوتی ہے.آیت کا پہلا حصہ دونوں ساعتو ں کے لئے بطوردلیل ہے.زمین وآسمان کی پیدائش قیامت کی بھی دلیل ہے اورنبیوں کی کامیابی اور ان کے دشمنوں کی تباہی کی بھی.پیدائش دنیا کی غرض قیامت کی اس طرح کہ اگرانسان کی زندگی صرف اس دنیا تک ختم ہوجاتی ہے.توگویا اس قدر بڑی دنیا اللہ تعالیٰ نے صرف اس لئے پیدا کی ہے کہ انسا ن اس میں پیداہوکچھ دن کھائے پئے اورپھر مرجائے.اوریہ خیال بالکل خلافِ عقل ہے.اس قدر بڑے نظام کا پیداکرنا ایک بہت بڑ ی غرض کے لئے ہی ہو سکتا ہے.اوروہ غرض پوری ہوتی اس دنیا میں نظرنہیں آتی.پس ضرور ہے کہ انسان کی زند گی اسی دنیوی حیات تک
Page 364
ختم نہ ہو.بلکہ اس نظام کی عظمت کے مطابق ایک بڑے زمانہ تک چلی جائے جس میں وہ ایک ایسے اعلیٰ مقام کوپالے جو اس نظام کی عظمت کے مطابق ہو.پیدائش دنیا قیامت کی دلیل ہے اگرغورکیا جا ئے توسارانظام توالگ رہا.اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سے چھوٹی چیزمیں ہی ایسے اسرار رکھے ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے.انسانی جسم کوہی لے لو اس کانظام کیسا پیچیدہ ہے.ہزاروں لاکھوں اطباء اورعلم تشریح کے ماہر اس کی حقیقت کومعلوم کرنے میں لگے ہوئے ہیں.لیکن اب تک ان امور کا احاطہ نہیں کرسکے جو جسم انسانی سے تعلق رکھتے ہیں.قرآن کریم کے نزول کے زمانہ کے بعد تویورپ نے سائنس میں بے انتہاکما ل حاصل کیا ہے.مگر اب تک انسانی جسم کے متعلق پورا احاطہ نہیں کرسکا.پھر اس قدر وسیع قوانین پر جس وجود کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کی پیدائش کے مقصد کو اس قدر حقیر بتانا جیساکہ قیامت کے منکر بتاتے ہیں کس طرح معقول سمجھاجاسکتاہے.اسی طرح یہ نظام انبیاء کی کامیابی اوران کے دشمنوں کی تباہی پر بھی دلالت کرتاہے.زمین کو آسمان سے جدا کردو.پھر اس کی کیاحالت ہوجاتی ہے.ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتی.پس جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں.کہ روحانی آسمان سے قطع تعلق کر کے بچ رہیں گے کیسے اندھے ہیں.جس طرح اس نظام کامل کاجز و رہتے ہوئے ہی زمین محفوظ رہ سکتی ہے اسی طرح روحانی نظام کا جزو بننے سے ہی انسان ہلاکت سے بچ سکتاہے ورنہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں.خصوصاًجبکہ وہ اس نظام پر حملہ آور ہو.تواس کی نجات قطعاًناممکن ہے.پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرو ں کو بتایا گیا ہے کہ آسمان روحانی سے قطع تعلق کرلینے کی وجہ سے ان کے سامان کسی کام بھی نہ آئیں گے بلکہ اب ان کی تباہی اورمسلمانوں کی ترقی کا وقت آن پہنچا ہے.اس آیت میں کس زورشور سے کفار کی تباہی کی خبر دی گئی ہے اورساتھ ہی یہ بتایاگیا ہے کہ اب وہ وقت آیا ہی چاہتاہے.اس کے بعد جس طرح جلد جلد حالات بدلے اورکفار مکہ کی تباہی کے سامان پیداہوئے.وہ ایک ایسانشان ہے کہ کسی الٰہی سلسلہ میں بھی اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی.کیونکہ یہ تباہی آسمانِ روحانی کے سب سے بڑے ستارے بلکہ سورج کی مخالفت اوراس سے قطع تعلق کے نتیجہ میں ظاہر ہوئی.اس سورۃ کا مکی ہونا زیادہ درست ہے اس آیت سے یہ معلوم ہوتاہے کہ جن لوگوں کاخیال ہے کہ یہ سورۃ مکی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی زیادہ درست ہے.کم سے کم یہ آیات تومعلوم ہوتاہے ضرور مکی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی ہیں کیونکہ ان میں مکہ والوں کی تباہی پر خاص زورہے اوراسے بہت قریب بتایا گیا ہے.سورہ نحل
Page 366
کے لفظ سے اس امرکی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم کسی قوم کوتباہ کرتے وقت ڈرا نہیں کرتے.کیونکہ ہم خلّاق ہیں یعنی بہت پیداکرنے والے ہیں تباہ کرنے سے ڈرتواس کو ہو جوپھر پیدانہ کرسکے مگر ہم توخلاق ہیں.ہرمفسد قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو کھڑاکردیتے ہیں.اورہماری بادشاہت میں کوئی کمی نہیںآتی اس جگہ اس قسم کامضمون بیان کیا گیاہے.جوحضرت موسیٰ علیہ السلام اورفرعون کے متعلق سورئہ زمر میں بیان کیاگیاہے وہاں فرعونیوں کی تباہی بیان کرکے فرماتا ہے کہ كَذٰلِكَ١۫ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ.فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَ الْاَرْضُ وَ مَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ.(الدخان : ۲۹.۳۰) یعنے اےموسیٰ!دیکھ ہم نے کس طرح اس قوم کو تباہ کردیا.اوران کی جگہ وہی عزت ایک اورقوم کو (یعنی خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو )دے دی اوران کی تباہی پر آسمان نہ رویا اورنہ زمین روئی یعنے نہ خدا تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی کمی آئی کہ اہل آسمان کواس پررنج ہوتا.اورنہ اہل زمین کو ان کی تباہی سے کوئی نقصان پہنچا نہ انہوں نے ان کی تباہی پر افسوس کیا کیونکہ انبیاء کے مخالف ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں.ان کی تباہی کے بعدباقی دنیا افسوس نہیں کرتی بلکہ امن کاسانس لیتی ہے.اور علیم کالفظ جو آخر میں رکھا ہے.اس میں اس امر کی طر ف اشارہ کیاہے کہ ان کی تباہی کے بعد دنیا میں جو ایک نیانظام قائم ہوگا اسے ہم جانتے ہیں.وہ ایسا اعلیٰ درجہ کانظام ہے کہ اسے دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی تباہی اورودسری قوم کے پیداکرنے پر رنج نہیں خوشی ہونی چاہیے.قرآن کریم کاکتنا کما ل ہے.ایک مختصرلفظ سے کس قدروسیع مطالب بیا ن کردیئے ہیں اورمسلمانوں کی حکومت کے اعلیٰ نظام کی طرف کس خوبی سے اشارہ کیا ہے قرآنی مطالب کی ترتیب بھی کیسی اعلیٰ ہے.شروع سورۃ میں فرمایاتھا ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ(الحجر :۴) ان کوچھوڑ دے کہ کھائیں.دنیوی فائدے اٹھائیں.اورلمبی لمبی امید وں میں پڑے رہیں یہ عنقریب جان لیں گے کہ ان کاکیا انجام ہوتاہے.اب آکر فرمایا.لو اب وہ گھڑی آہی پہنچی.اوران کے کھانے پینے اوربڑی بڑی امیدیں رکھنے کا زمانہ ختم ہوگیا.یہ مضمون کازورایسا ہی ہے جیسے کہ آبشار کاپانی جب گرنے کے مقام پر آتا ہے تویکدم اس میں زور پیداہو جاتا ہے.ایک اعتراض کا جواب اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ.میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ( صلی اللہ علیہ وسلم )کی ترقی کے ظاہری سامان کہاں سے پیداہوں گے.ان کویاد رکھناچاہیے کہ اللہ تعالیٰ خلّاق ہے.جب وہ وقت آجائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ان لوگوں کی تباہی اورمسلمانوں کی ترقی کافیصلہ کرلے گی.تواللہ تعالیٰ جو خلاق ہے خود ہی سب سامان پیداکردے گا.
Page 367
آنحضرت ؐ کی ترقی کی ابتداو انتہاء چنانچہ اس پیشگوئی کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے چند لوگوں کے دلوں میں حج کی رغبت پیداکی.جب وہ حج کے لئے آئے توانہوں نے محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا اورآپ سے ملے پھر جاکر اپنی قوم کو ساراحال سنایا.اوروہاں سے ایک وفد آگیا.جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے درخواست کی.کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہمارے شہر میں چلے آئیں.اورآپ نے خدا تعالیٰ کے اذن سے ان کی اس درخواست کوقبول کرلیا(سیرۃ النبی لابن ہشام امر العقبۃ الثانیۃ).اورچند دن کے اند ر اندر وہ جو مکہ میں کوئی سر چھپانے کی جگہ نہ پاتے تھے.ایک زبردست حکومت کے بانی ہوگئے اوروہ دنیوی سامان بھی پیداہوگئے.جن کے نہ ہونے کی وجہ سے اہل مکہ اپنی فتح یقینی سمجھتے تھے.اوروہ اس تغیر عظیم کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے.وَ لَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ۰۰۸۸ اورہم نے یقیناً تجھے دہرائی جانے والی سات(آیات)اور(بہت بڑی)عظمت والاقرآن دیاہے.حلّ لُغَات.اَلْمَثَانِی اَلْمَثَانِیْ کے معنے ہیںآیَاتُ الْقُرْآنِ.قرآن مجید کی آیات.مِنَ الْوَادِیْ مَعَاطِفَہٗ یعنی مَثَانِی الْوَادِیْ.وادی کے موڑوں کوکہتے ہیں.مَثْنَی الْاَیَادِیْ کے معنے ہیں.اِعَادَۃُ الْمَعْرُوْفِ مَرَّتَیْنِ فَاَکْثَرَ یعنی بار بار احسان کرنے کو مَثْنَی الْاَیَادِیْ کہتے ہیں.اس میں دوکی شرط نہیں.بلکہ دویادوسے زیادہ مرتبہ احسان ہو.مَثَانی الشَّیْ ءِ.قُوَاہٗ وَطَاقَاتُہٗ.مَثَانِی الشَّیْءِ سے مراد اس کی قوتیں ہیں.(اقرب) سبع مثانی کے متعلق مختلف صحابہ اور علماء کا خیال حضرت عمر ؓ ،علی ؓ،ابن مسعودؓ،ابن عباسؓ اورعلماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ سَبْعَ مَثَانِیْ سے مراد اس جگہ سورہ فاتحہ ہے.اورابوہریرہ سے روایت ہے کہ عَنِ النَّبِیّ صَلَی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنَّھا(ای الْفَاتِحَۃُ) اَلسَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَاُمُّ الْقُرْاٰنِ وَفَاتِحَۃُ الْکِتَابِ وَسُمِّیَتْ بِذٰلِکَ لِاَنَّھَاتُثَنّٰی فِیْ کُلِّ رَکْعَۃٍ.کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ سورہ فاتحہ سبع مثانی ہے اور امّ القرآن اورفاتحۃ الکتاب بھی اسے اس لئے مثانی کہتے ہیں کہ یہ ہررکعت میں دہرائی جاتی ہے قِیْلَ لِاَنَّھَا یُثْنَی بِہَاعَلَی اللّٰہِ تَعَالیٰ.کہ اس کومثانی اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے خدا کی ثناکی جاتی ہے.ان معنوں کو زجاج نحوی نے جائزقراردیاہے لیکن ابن عطیہ نے قواعد صرف کے خلاف قرار دیا ہے.علامہ ابوحیان لکھتے ہیں
Page 368
کہ یہ اعتراض درست نہیں.کیونکہ مثانی مُثْنٰی کی بھی جمع ہے جو اثنٰی رباعی سے مُفْعَل کے وزن پر ہے اورا س کے معنے ثناء کے ہیں.یعنے جس میں اللہ تعالیٰ کی ثناکا مضمون اچھی طرح بیان کیاگیا ہے ( بحر محیط زیر آیت ھذا).ان معنوں کے روسے آیت کے معنے ہوئے ہم نے تجھ کو سات آیتوں والی وہ سورۃ دی ہے کہ جوبار بار دہرائی جاتی ہے یاجس میں سات آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ثناکامل طورپر بیان کی گئی ہے.تفسیر.مثانی کے اصل معنی جب یہ فرمایا کہ یہ لوگ اب تباہ ہونے کو ہیں اوران کی جگہ مسلمانوں کو برتری ملنے والی ہے.توساتھ ہی فرمایاکہ ان کی طرف سے توجہ ہٹاکر اب تم مسلمانوں میں قرآن کی ترویج اورتعلیم پر زیادہ زور دوتاکہ کامیابی کے دنوں کے آنے سے پہلے یہ اس کام کے لئے جو ان کے ذمہ لگنے والا ہے تیار ہوجائیں چنانچہ فرمایا ہم نے تم کو سور ہ فاتحہ جیسی نعمت دی ہے جو صرف سات آیات ہیں.اورمثانی ہیں مثانی کے معنے جیساکہ حل لغات میں بتائے جاچکے ہیں.کسی شے کی قوت اورطاقت کے بھی ہوتے ہیں.اورسورہ فاتحہ کو مثانی کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اس میں قرآن کریم کی قوتوں اورطاقتوں کانچوڑہے یعنے ہیںتوسات مختصر آیات لیکن سارے قرآن کے مطالب اجمالاً اس میں آگئے ہیں.قرآن عظیم سے مراد بقیہ قرآن بھی ہو سکتا ہے قرآن عظیم سے مراد بقیہ قرآن بھی ہو سکتا ہے اورمراد یہ ہوگی کہ سورئہ فاتحہ بھی دی جو اجمالی قرآن ہے اورتفصیلی قرآن بھی دیا.اوراس سے مراد خود سورہ فاتحہ بھی ہوسکتی ہے.اس صورت میں اس سے یہ مطلب ہوگا کہ سورئہ فاتحہ قرآن کریم کا ایک بڑامہتم بہ حصہ ہے.اورقرآن سے ساراقرآن نہیں بلکہ حصہ قرآن مراد لیا جائے گااوریہ عام محاورہ ہے کہ کبھی جزو کے لئے کل کالفظ بول دیاجاتاہے جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں.قرآن سنائو اوراس سے مراد ساراقرآن سنانا نہیں ہوتابلکہ اس کاکچھ حصہ سنانا مطلوب ہوتاہے.پس القرآن العظیم کا لفظ سورئہ فاتحہ کے متعلق اس اظہار کے لئے ہے کہ وہ قرآن عظیم کاحصہ ہے اس سے باہر نہیں.ان معنوں سے ان لوگوں کے خیالات کی تردید ہوتی ہے جویہ خیال کرتے ہیں کہ سورئہ فاتحہ قرآن کاحصہ نہیں.حدیث میں سورہ فاتحہ کا نام سبع مثانی رکھا گیا ہے احادیث میں بھی سورۃفاتحہ کا نام قرآن عظیم بتایاگیاہے.چنانچہ مسند احمد حنبل میں ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھِیَ اُمُّ الْقُراٰنِ وَھِیَ السَّبْعُ المَثَانِیْ وَھِیَ القُرْاٰنُ الْعَظِیْمُ(مسند احمد بن حنبل مسند أبی ھریرۃؓ)یعنی سورۃ فاتحہ ام القرآن بھی ہے اورسبع المثانی بھی ہے اورقرآن عظیم بھی ہے.
Page 369
مثانی اور قرآن عظیم سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن عظیم سارے قرآن کانام نہیں.دونوں ہی معنے ایک وقت میں کئے جاسکتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں.یہ بھی کہ سور ۃ فاتحہ قرآن عظیم ہے اوریہ بھی کہ ساراقرآ ن قرآن عظیم ہے.کیونکہ یہ دونوں معنے مختلف نقطہ نگاہ کی وجہ سے ہیں.اوراپنی اپنی جگہ پر درست ہیں.اگرقرآن عظیم کے معنے سارے قرآن کے کئے جائیں تویہ مطلب ہوگاکہ ہم نے تم کو اجمالی قرآن یعنے سورۃ فاتحہ بھی دی ہے اوراس کے علاوہ ایک تفصیلی قرآن بھی دیا ہے.پس اس کی تعلیم کی طرف توجہ کرو.اوران لوگوں سے بحث مباحثہ کاخیال جانے دو اب وقت آگیا ہے کہ مسلمانوںکو مطالب قرآن خوب زور سے سکھائے جائیںتاکہ وہ نئے نظام کے سنبھالنے کے اہل ہوجائیں.لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَ اوروہ جو ہم نے ان میں سے کئی گروہوں کو عارضی نفع کا سامان دیاہے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کرنہ دیکھ اوران لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ۰۰۸۹ (کی تباہی)پر غم نہ کھا.اورمومنوں پر اپنا (شفقت کا)بازو جھکائے رکھ.حل لغات.تَمُدَّنَّ: تَمُدَّنَّ مَدَّ سے مضارع کاصیغہ ہے اورمَدَّ نَظَرَہٗ اِلَیْہِ کے معنے ہیں طَمَحَ بِبَصَرِہٖ اِلَیْہِ کہ اس کی طرف ٹکٹکی لگاکر دیکھا(اقرب) پس لَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ کے معنے یہ ہوں گے کہ توان کی ترقیات کی طر ف ٹکٹکی لگاکر نہ دیکھ.تفسیر.آیت لَا تَمُدَّنَّ کے غلط معنوں کی تردید بعض لوگوں نے اس آیت کے یہ معنے کئے ہیں کہ بصریٰ اوراوزعات سے بنوقریظہ اوربنونظیر کے سات قافلے آئے تھے وہ کپڑوں اورعطروں اورجواہرات پر مشتمل تھے انہیں دیکھ کر صحابہؓ نے کہا کہ کاش یہ مال ہمارے پاس ہوتا تو ہم کو اس سے طاقت حاصل ہوتی.اورہم اسے خدا کی راہ میں خرچ کرتے (تفسیر القرطبی زیر آیت ھذا).یہ معنے میرے نزدیک درست نہیں.اوران کے غلط ہونے کا یقینی ثبوت یہ ہے کہ سب مفسرین متفق ہیں کہ یہ سورۃ ساری کی سار ی مکی ہے (تفسیر القرآن از ویری اور ترجمہ القرآن راڈویل) حتی کہ عیسائی مستشرقین تک یہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ یہ سورہ سب کی سب مکی ہے.پھر جب
Page 370
یہ سورہ مکی ہے توبنوقریظہ اوربنونظیر کے قافلوں کودیکھ کر مسلمانوں کاایسی خواہش کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ بنو قریظہ اوربنونظیر کی حالت تو مسلمانوں نے ہجرت کے بعد دیکھی تھی.مکہ میں نازل ہونے والی سورۃ میں اس کا ذکر کیونکر آگیا؟نیز سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم مخاطب ہیں.صحابہ تومخاطب نہیں.اورآپؐ کی طرف ایسی خواہش منسوب کرنا میرے نزدیک توکسی صورت میں جائز نہیں بلکہ سو ء ادب ہے.نیز جبکہ اس سورۃ میں زور ہی اس امر پر ہے کہ ہم مسلمانوں کی ترقی کے سامان خود پیداکریں گے تورسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے د ل میں ایساخیال پیداہی کس طرح ہوسکتاتھا کہ خدا تعالیٰ توکہے کہ اس بارہ میں توہم پرتوکل رکھ اور رسول لوگوں کے اموال کودیکھ کر کہے کہ یہ مال ہمارے پاس ہوتاتوخوب ترقی کرتے.اسے کونسی عقل تسلیم کرسکتی ہے.آیت لَا تَمُدَّنَّ کا مطلب اصل بات یہ ہے کہ اِنَّ السَّاعَۃَ لَاٰتِیَۃٌ میں کفار کے نظا م کے ٹوٹنے کااشارہ تھا.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے دل کوجو نہایت حساس تھا اورجس میں اپنی قو م کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی.لازماً یہ صدمہ ہوناتھا کہ اب میری قوم یا اس کے عمائد ایمان سے محروم رہ جائیں گے اورتباہ کردیئے جائیں گے چنانچہ آپؐ ان صنادیدکی حالت کو دیکھ کر جن پر مکہ کے نظام کا مدار تھا.سخت افسوس کرتے ہوں گے کہ کاش یہ لوگ تباہ نہ ہوتے اورجس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کودنیا میں بڑا بنایاہے اللہ تعالیٰ ان کو دین میں بھی بڑابناتاتواچھا ہوتااوریہ خواہش نہایت پاکیزہ ہے.نبی کبھی کسی کی تباہی پر خوش نہیں ہوتا.بلکہ چاہتا ہے کہ سب ہی ایما ن لے آئیں.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم تو اس خواہش میں اس قد ر بڑھے ہوئے تھے کہ آپ کی نسبت قرآن کریم میں آتاہے لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ اَلَّا یَکُوْنُوْا مُؤُمِنِیْنَ(الشعراء:۴) اے محمد!(رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ) تُوتو شائد اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کرلے گا.کہ یہ لوگ سب کے سب مسلمان کیوں نہیں ہوجاتے.پس آپؐ کے ان شریف جذبات کو اس خبر سے ٹھیس لگی ہوگی.لَا تَمُدَّنَّ کے الفاظ کفا ر کی تباہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ؐ کے لئے بطور تسلی ہیں پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے یہ الفاظ بیان فرمائے.اورکہا کہ تجھے اپنی قوم کے اکابر کی تباہی کی خبر سن کر افسوس ہوگا.کیونکہ تُو ان کی ہدایت کی زبردست خواہش رکھتا ہے مگراب ہم ان کی تباہی کافیصلہ کرچکے ہیں.پس اب ان لوگوں کے لئے افسوس کرناچھوڑ دے.اوران کی ظاہر ی بڑائیوں کا خیال نہ کر.اب تو تیرے رب نے یہ فیصلہ کرلیا ہے کہ ان کو چھوٹاکردے اورتباہ کردے.پس اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ ان کے اموال کولالچ کی نگاہ سے نہ دیکھ.بلکہ یہ فرماتا ہے کہ ان کی ظاہری شان وشوکت دیکھ کر یہ افسو س نہ کر کہ اب عذاب الٰہی ان کو کنگال اورتباہ کر
Page 371
دے گا.اوران کی حشمت جاتی رہے گی.چنانچہ آیت کاآخری حصہ بھی انہی معنوں کی تائید کرتا ہے کیونکہ اس میں یہ فرمایاگیا ہے کہ وَلَاتَحْزَنْ عَلَیْہِمْ یعنے ان کی تباہی پر غم نہ کر.لَا تَمُدَّنَّ کے معنی کفار کے اموال کی لالچ کی نگاہ سے دیکھنے کے نہیں اس جملہ کے ہوتے ہوئے وہ معنے جو بعض لوگوں نے کئے ہیں کس قدرخلاف عقل ہوجاتے ہیں.کیونکہ اگر وہ معنےصحیح ہیں.توآیت کامضمون یہ بن جائے گا کہ اے محمد رسو ل اللہ !توان کے مالوں کو دیکھ کر لالچ نہ کر اوریہ خواہش نہ کر کہ وہ اموال تجھ کو مل جائیں.اورتو ان کی تباہی پر غم نہ کھا.یہ معنے کیسے لغو ہیں.اورکس طرح ان کاایک حصہ دوسرے حصہ کورد کرتا ہے.لیکن جو معنے میں نے کئے ہیں وہ ساری آیت کے مضمون کو ایک دوسرے کامؤید بنادیتے ہیں.جوشخص دوسرے کے مال کو لینا چاہتا ہے وہ اس کی تباہی پر غمگین کیونکر ہو سکتا ہے و ہ تواپنی خواہش سے عملًا اس کی تباہی کی دعاکرتا ہے.وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤمِنِیْنَ کے الفاظ بھی میرے کئے ہوئے معنوں کی تائید کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ معنے مراد ہوں جن کو میں نے رد کیا ہے.تواس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ کفار کے متعلق یہ خواہش نہ کر کہ ان کامال تجھ کو مل جائے اوران کی تباہی پر افسوس نہ کر.اورمومنوں کی تربیت کی طرف پوری توجہ کر.اگر یہ معنے ہوں توآیت کے سب ٹکڑے بے ربط ہوجاتے ہیں.لیکن میرے کئے ہوئے معنوں کی صورت میں یہ الفاظ بھی آیت کے دوسرے حصوں سے کامل طورپر مربوط معلوم ہوتے ہیں.کیونکہ ان میں یہ بتایا گیاہے کہ بڑے بڑے کفار کی تباہی کا ہم فیصلہ کرچکے ہیں.پس اب ان کی جاتی ہوئی شان کو دیکھ کرتوغم نہ کر بلکہ جولوگ ان کی جگہ لینے والے ہیں یعنے مومن ان کی تربیت کی طرف متوجہ ہوجا کہ اب دنیا کی ترقی پرانے سرداروں کے بچانے سے ممکن نہیں.بلکہ اس کامدار ان لوگوں کی صحیح تربیت پر ہے.آیت وَاخْفِضْ سے ہجرت کی طرف اشارہ وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤمِنِیْنَ سے ایک باریک اشارہ ہجرت کی طرف بھی کیاگیا ہے.کیونکہ مومنوں کی کامل تربیت ایک نظام کو چاہتی ہے قرآن کریم کے وہ احکام جونظام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے.ان کاعملی اجراء مکہ میں نہیں ہوسکتاتھا.پس یہ کہہ کر کہ اب تومومنوں کی ایسی تربیت کی طرف توجہ کر کہ آگے چل کر یہ دنیا کانظام سنبھال لیں.اس طر ف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب ہم تجھے اس جگہ لے جانے والے ہیں جہاں تجھے اس تربیت کاموقعہ پوری طرح مل جائے گا.خلاصہ یہ کہ آنکھیں اُٹھا اُٹھا کر دیکھنے سے اس لئے منع نہیں کیا گیا.کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم
Page 372
کو ان کے مالوں کی لالچ تھی.بلکہ اس حسرت سے دیکھنے سے منع کیاگیا ہے کہ اب سرداران عرب کی حشمت جاتی رہے گی اوروہ ایمان سے محروم رہ جائیں گے.اوران کے اموال ان کو تقویٰ میں بڑھانے کی بجائے ان کی ہلاکت کاموجب ہوجائیں گے.وَ قُلْ اِنِّيْۤ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُۚ۰۰۹۰ اور(لوگوں سے )کہہ (کہ )میں ہی کھول (کھول )کر بیان کرنےوالاکامل نذیر ہوں.تفسیر.یعنے اب توبانگ بلند سے ان کو یہ سنادے کہ میں ہاں میں ہی کھلاکھلا نذیر ہوں.یعنی اس وقت خدا تعالیٰ نے انذار کاکام میرے ہی سپرد کیا ہواہے اس لئے میں الٰہی منشاء کے ماتحت اعلان کرتاہوں کہ تمہاری تباہی کا وقت آگیا ہے.كَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَۙ۰۰۹۱ اس لئے کہ ہم نے باہم بانٹ لینے والوں کے متعلق (اپناانذاری کلام)نازل کیا ہے.حلّ لُغَات.المقتسمین :اَلْمُقْتَسِمِیْنَ اِقْتَسَمَ سے اس کا فاعل مُقْتَسِمٌ آتاہے اور مُقْتَسِمُوْن اس کی جمع ہے.اِقْتَسَمُوا المال بَیْنَہُمْ کے معنی ہیں.اَخَذَ کُلٌّ قِسْمَہُ.انہوں نے مال تقسیم کرلیا اورہرایک نے اپنااپناحصہ لے لیا (اقرب) تَقَاسَمَا الْمَالَ.اِقْتَسْمَاہُ بَیْنَہُمَا.انہوں نے آپس میں مال تقسیم کرلیا.فَالْاِقْتِسَامُ وَالتَّقَاسُمُ بِمَعْنَی وَاحِدٍ.یعنی ان معنوں کے روسے اقتسام اورتقاسم ہم معنی ہیں (تاج)پس مُقْتَسِمُوْنَ کے معنی ہوں گے تقسیم کرنے والے.مراد آنحضر ت کی دشمنی کے فرائض باہم تقسیم کرنےوالوں سے ہے.تفسیر.عام طورپر اس آیت کے یہ معنی کئے جاتے ہیں ’’جس طرح ہم نے مُقْتَسِمِیْنَ پر نازل کیا ہے.‘‘ (تفسیر لامام رازی زیر آیت ھذا) كَمَاۤ اَنْزَلْنَا الخ میں ک کے معنی تعلیل کے ہیں مگر میرے نزدیک اس جگہ ک کے معنی تعلیل کے ہیں اورکاف کا یہ استعمال لغت عربی سے ثابت ہے (اقرب) خود قرآن کریم میں بھی ان معنوں میں ک متعددجگہ استعمال ہواہے مثلاً فرماتا ہے وَاذْکُرُوْہُ کَمَا ھَدٰکُمْ(البقرۃ :۱۹۹) اللہ تعالیٰ کو یاد کروکیونکہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے.پس
Page 373
ک کے ان معنوں کے رو سے آیت کے معنے یہ ہوں گے کیونکہ ہم نے (عذاب) مُقْتَسِمِیْنَ پراُتاراہے.آیت كَمَاۤ اَنْزَلْنَا الخ پہلی آیت سے متعلق ہے اوریہ آیت پہلی آیت سے متعلق سمجھی جائے گی.اوردونوں آیتوںکا مطلب یہ ہوگا.کہ اے محمد! صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم توان لوگوں سے کہہ دے کہ میں نذیر عریان ہوں.کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقتسمین کے لئے یہ عذاب اُتارنے کافیصلہ کردیا ہے.جیساکہ ظاہر ہے.ان معنوں سے مفہوم بہت صاف ہو جاتا ہے.لیکن اگر ک کے معنے ’’جس طرح‘‘ کئے جائیں تومطلب واضح نہیں رہتا.کیونکہ اس صورت میں عبارت یہ بنتی ہے کہ ان سے کہہ دے میں نذیر عریان ہو ں.جس طرح ہم نے مقتسمین پر اتاراہے.یہ معنے جیساکہ ظاہر ہے کوئی صحیح مفہوم پیدا نہیں کرتے.اسی وجہ سے مفسرین کو اس آیت کے معنے کرنے میں سخت دقت ہوئی ہے اورلمبی لمبی توجیہیں کرکے انہیں کوئی معنے نکالنے پڑے ہیں.مفسرین کو اس آیت کے معنوں میں دقت مُقْتَسِمِیْنَ کے معنوں کے بارہ میں بھی مفسرین کوبڑی دقت پیش آئی ہے.انہوں نے اس آیت کے معنے یہ کئے ہیں.کہ جس طرح ہم نے ان پر عذاب اتاراہے.جنہوںنے رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں(الکشاف القرطبی زیر آیت کما انزلنا علی المقتسمین).بخاری میں بھی یہ معنی بیان کئے گئے ہیں (بخاری کتاب التفسیر سورۃ الحجر باب قولہ الذین جعلو ا القرآن عضین) مگر میرے نزدیک عربی زبان کی رو سے یہ معنے درست نہیں.کیونکہ اِقْتَسَمَ کے معنے قسمیں کھانے کے نہیں ہیں.بلکہ تقسیم کرنے کے ہیں.چنانچہ اقرب میں ہے اِقْتَسَمُواالْمَالَ بَیْنَہُمْ ای اَخَذَ کُلٌّ قِسْمَہُ یعنے جب اِقْتَسمَ الْمَالَ کا لفظ بولیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے تقسیم کرلیا اور ہر اک نے اپنا اپنا حصہ لے لیا.تاج العروس میں ہے تَقَاسَمَا الْمَالَ.اِقْتَسَمَاہُ بَیْنَہُمَا یعنے تَقَاسَمَا الْمَالَ کہیں تو اس کے معنے اقْتَسَمَا کے یعنے آپس میں تقسیم کر لینے کے ہوتے ہیں.غرض اِقْتَسمَ کے معنے تاج العروس میں تقسیم کرنے کے لکھے ہیں.اقتسم کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں اب سوال یہ ہے کہ پھر لوگوں کو یہ دھوکا کیونکر لگا کہ اس کے معنے باہم قسمیں کھانے کے ہوتے ہیںتو اس کا جواب یہ ہے کہ تَقَاسَما کے ایک معنے قسمیں کھانے کے ہیں اور دوسرے معنی تقسیم کرنے ہیں.ان معنوں کوبتانے کے لئے اہل لغت لکھتے ہیں کہ تَقَاسَما اور اِقْتَسَما ہم معنے الفاظ ہیں.ان کا مطلب یہ ہے کہ تَقَاسَما.اقتَسَما کی طرح تقسیم کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.نہ یہ کہ اِقْتَسَمَ بھی تَقَاسَمَا کی طرح قسمیں کھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.مفسّرین نے اس مشابہت سے دھوکا کھایا ہے حتّٰی کہ زمخشری جیسے ادیب نے بھی دھوکا کھا یا ہے میرے دعویٰ کی تصدیق تاج العروس کے ان الفاظ سے ہوتی ہے
Page 374
تَقَاسَمَا الْمَالَ.اِقْتَسَمَاہُ بَیْنَہُمَا فَالْاِقتسامُ وَالتَّقَاسُمُ بمعنَی وَاحِدٍ یعنے ’’تَقَاسَمَا الْمَالَ کے معنے اِقْتَسَمَا الْمَالَ کے ہیں یعنے آپس میں مال تقسیم کرلیا.پس اِقْتِسَامَ اورتَقَاسُمَ ایک ہی معنے رکھتے ہیں‘‘.اس عبارت سے ظاہر ہے کہ تاج العروس والے کے نزدیک دونوں کااشتراک تقسیم کرنے کے معنوں میں ہے نہ کہ قسموں کے کھانے کے متعلق.چنانچہ آگے تاج العروس والے نے اس آیت کو بطورشہادت پیش کیا ہے گوآگے ابن عرفہ کایہ قول بھی نقل کیا ہے کہ مُقْتَسِمِیْنَ کے معنے تَقَاسَمُوا کے ہیں.لیکن اوپر کی تشریح کے ماتحت صاف ظاہر ہے کہ تاج والا ان معنوں کولغت کے معنی نہیں قرار دیتا بلکہ تفسیری معنے قرار دیتاہے.مقتسمین سے مراد آنحضرت ؐ کے خلاف تدابیر کرنے والے ہیں اس تمہید کے بعد میں یہ بتاتا ہوں کہ مقتسمین سے کیا مراد ہے.میرے نزدیک تقسیم کرنے والوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کے کام تقسیم کرنے والے مراد ہیں اورمطلب یہ ہے.کہ جن لوگوں نے تیرے خلاف تدابیر کرنے کے کاموں کوتقسیم کرلیا ہے.کسی نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لی ہے کہ مکہ کے باہر کھڑاہوکر لوگوں کو ورغلائے.کسی نے یہ ڈیوٹی لے لی ہے کہ یہ شور مچاتاپھر ے کہ اگر سچاہوتاتو ہم جو رشتہ دار ہیں کیوں نہ مانتے.کسی نے مسلمانوں کو دکھ دینے کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی ہے کسی نے دوسری اقوام میں پرپیگنڈاکرنے کی ڈیوٹی.سوان سب لوگوں کے لئے ہم نے عذاب کافیصلہ کرلیا ہے بعض لوگوں نے یہ معنے کئے ہیں کہ قرآن کو انہوں نے تقسیم کرلیا ہے کہ بعض حصہ کومانتے ہیں اوربعض کو نہیں (فتح البیان و قرطبی).مگر یہ معنے بھی درست نہیںمعلوم ہوتے.آیت کا اصل مطلب کیونکہ مُقْتَسِمْ کے معنے توباہم تقسیم کرلینے کے ہیں.اور کسی حصہ پر ایمان لانااور کسی کورد کردینا ’’باہم تقسیم‘‘کامفہوم ادانہیں کرتا.پس کسی جزوپرایمان لانا اور کسی پر نہ لانا گوبعض کفار کاشیوہ ہے اورقرآن کریم میں مذکورہے.مگرا س آیت میں اس مفہو م کی طرف اشارہ نہیں ہے.الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ۰۰۹۲ جنہوں نے قرآن کو جھوٹی باتوں کامجموعہ قرار دیا.تفسیر.عِضِیْن کے معنے جھوٹوں کا مجموعہ.عِضِیْنٌ اورعِضُوْنَ عِضَۃٌ کی جمع ہیں اورعِضَۃٌ کالفظ عَضٰی یَعْضُوْاعَضْوًا سے بھی نکلا ہے جس کے معنے ٹکڑے کرنے کے ہوتے ہیںاورعَضَہَ یَعْضَہُ عَضْہًا
Page 375
سے بھی نکلا ہے جس کے معنے جھوٹ بولنے کے ہوتے ہیں.پس عِضَۃٌ کے معنے جھوٹ کے بھی ہیں اورٹکڑے کے بھی اورعِضِیْنَ کے معنے بہت سے جھوٹوں کے بھی ہیں اورٹکڑوں کے بھی.اگر عِضَۃٌ.عَضٰی یَعْضُوْا کے مادہ سے مشتق سمجھاجائے تب بھی اہل لغت کے نزدیک اس کے معنے ’’ٹکڑہ‘‘کے علاوہ ’جھوٹ‘ کے بھی ہوتے ہیں.(اقرب) غرض ایک مادہ کے روسے عضین کے معنے ’ٹکڑوں ‘کے ہیں.اوردونوں مادوں کے روسے اس کے معنے ’جھوٹوں‘ کے ہیں.اور میرے نزدیک دوسرے معنے اس آیت میں زیادہ درست معلوم ہوتے ہیں.مگران معنوں کے سمجھنے کے لئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جَعَلَ کے ایک معنی ظَنَّ کے بھی ہوتے ہیں یعنی ایساسمجھا.چنانچہ عربی کامحاورہ ہے جَعَلَ الْحَقَّ بَاطِلًا یعنے سچ کو جھوٹ سمجھا (اقرب) اس آیت کا پہلی آیت سے تعلق اورعضین کے معنے جھوٹ کرنے کی صورت میں جَعَلَ اس آیت میں انہی معنوں میںمستعمل ماننا پڑے گا.اورترجمہ یہ ہوگا.کہ ’’وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو جھوٹوں کامجموعہ سمجھ رکھا ہے ‘‘ اورگزشتہ آیتوں سے مل کر مفہوم یہ بنے گا کہ اس موعود عذاب کی خبر ان کو دے دے جنہو ںنے تیری مخالفت کی ڈیوٹیاں تقسیم کررکھی ہیں.اورقرآن کریم کوجھوٹوں کامجموعہ سمجھ رکھا ہے اوربتادے کہ اب ان لوگوں کی تباہی کا وقت آپہنچاہے.یہ معنے ایسے واضح ہیں کہ ان سے تمام و ہ مشکلات دورہوجاتی ہیں جودوسرے مفسرین کو پیش آئی ہیں.فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَۙ۰۰۹۳عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰۰۹۴ سوتیرے رب کی قسم ہم ان سب سے باز پرس کریں گے ان کاموں کے متعلق جو و ہ کیا کرتے تھے.تفسیر.لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ سے مراد محاسبہ اور سزا ہے فرماتا ہے کہ تیرے رب ہی کی قسم! اب ایسے سب لوگ سزاپائیں گے.اورہم ان سب سے پوچھیں گے پوچھنے کامطلب اس جگہ وہی ہے جو پنجابی میں پوچھوں گا کاہوتاہے.یعنی ان کی شرارتوں کااب حساب لیں گے اوران کو سخت سزادیں گے.
Page 376
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ۰۰۹۵ سو جس بات (کے پہنچانے)کاتجھے حکم دیاجاتاہے وہ کھو ل کر (لوگوں کو)بتادے اوران مشرکو ں (کی بات)سے اعراض کر.حلّ لُغَات.اِصْدَعْ:اِصْدَعَ صَدَعَ سے امر کاصیغہ ہے.اورصَدَعَہٗ صَدْعًا کے معنے ہیں.شَقَّہٗ.کسی چیز کوپھاڑ دیا.وَقِیْلَ شَقَّہُ بِنِصْفَیْنِ اوربعض نے کہا ہے کہ اس کودوحصوں میں تقسیم کردیا.وَقِیْلَ شَقَّہٗ وَلَمْ یَفْتَرِقْ اوربعض کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پھاڑ دیا لیکن و ہ دوٹکڑے نہ ہوئی.صَدَعَ الْاَمْرَ.کَشَفَہٗ وبَیَّنَہٗ: بات کوکھول دیا اورواضح کردیا.صَدَعَ بِالْحَقِّ وَبِالْحُجَّۃِ:تَکَلَّمَ بِھَاجِھَارًا.حق اورحجت کاعلی الاعلان اظہار کیا.صَدَعَ بِالْاَمْرِ اَصَابَ بِہٖ مَوْضِعَہٗ وَجَاھَرَ بِہٖ مُصَرَّحًا کہ کسی کام کو برمحل کیا.اوراس کی بآواز بلند تصریح کی صَدَعَ الْاَمْرَ بِالْحَقِّ.فَصَلَہٗ.کسی معاملہ کادرست فیصلہ کیا.(اقرب) تفسیر.فَاصْدَعْ میں اسلامی حکومت اور شریعت کے عملی اجراء کی خبر دی گئی ہے صَدَعَ بِالحقّ کے معنے حق کے ساتھ فیصلہ کرنے بھی ہوتے ہیں.اورصَدَعَ کے معنے کھول کر بیان کرنے کے بھی ہوتے ہیں.دونوں معنے یہاں چسپاں ہوتے ہیں.اورآیت کامطلب یہ ہے کہ جب خدئی فیصلہ ان کی ہلاکت اورمسلمانوں کی ترقی کی نسبت جاری ہوچکا ہے تواس امر کو خوب کھول کھول کر انہیں سنادے اورمشرکوں سے بحث مباحثہ چھوڑ دے.اسی طرح اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے (اوریہی ان معنوں کے ساتھ زیادہ چسپاں ہوتاہے جومیں اوپر کی آیات کے بیان کرچکاہوں)کہ اب تُواللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر.یعنے تجھے اب ہم ا س امر کا موقع دینے والے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام کا اجراء عملاً شروع ہو جائے.پس تواللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلوںکو جاری کردے اورمشرکوں کی پرواہ نہ کر اس آیت میں بھی گویا مدینہ کی ہجرت اوراسلامی حکومت کی خبر دی گئی ہے.
Page 377
اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَۙ۰۰۹۶ ہم یقیناً تجھے ان تمسخر کرنے والوں(کے شر)سے محفوظ رکھیں گے الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ١ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ۰۰۹۷ جواللہ(تعالیٰ)کے ساتھ کوئی (نہ کوئی )اورمعبود بنارہے ہیں.سوو ہ عنقریب (اس کا نتیجہ)معلوم کرلیں گے.تفسیر.اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَکا حکم دینے کی وجہ یعنی اب تجھے ان لوگوں کی طرف توجہ کی اس لئے ضرورت نہیں کہ اب بحث مباحثہ والے جوابوں کی جگہ ہم ان کو آسمانی نشانوں کے ساتھ جواب دینا چاہتے ہیں اورتجھ پر ہنسی کرنے والوںکو عبرتناک سزائیں دینا چاہتے ہیں.ان کوسوچنا چاہیے تھاکہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے شریک بنارہے ہیں اوراس کی ہتک کررہے ہیں تووہ کب تک ان کی اس حرکت کو برداشت کرتاچلاجائے گا.سَوْفَ یَعْلَمُوْنَ کی پیشگوئی کا قومی اور فردی ظہور قومی طور پر تویہ پیشگوئی بعد ہجرت کفار کی شکست اورذلت سے پوری ہوئی.فردی طور پر بھی ا س کاعجیب شاندار طورپر ظہور ہوا.عروہ بن زبیر کی روایت ابن اسحاق نے لکھی ہے (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا) آنحضرت ؐ پر ہنسی اڑانے والوں کا انجام کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی اُڑانے والے پانچ رؤساء تھے ولید بن مغیرہ.عاص بن وائل.اسود بن عبدیغوث اوراسودبن المطلب اور حرث بن طلاطلہ.ان کے بارہ حضرت جبریل کشف میں رسول کریم صلعم کو نظرآئے اوراسود بن عبدیغوث کے پیٹ کی طرف اشارہ کیااسے استسقاء ہو گیا اوروہ اس سے مرگیا.ولید بن مغیرہ کے پیر کی طرف اشارہ کیا اسے ایک پرانا زخم تھا جومندمل ہوچکاتھا اس کے بعد وہ زخم پھٹ گیا اورو ہ ا س سے مرگیا.اورعاص بن وائل کے پائوں کے تلوں کی طر ف اشار ہ کیا وہ چند دن بعد گدھے پر سوار طائف کوجارہاتھا کہ تلے میں کوئی چیز کھُب گئی اوروہ اس سے مرگیا.اورحرث بن طلاطلہ کے سر کی طرف اشارہ کیا وہ سرکے زخم سے ہلاک ہوگیا.اوراسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اوروہ اندھاہوکرمرگیا.یہ روایت سعید بن جبیر اورعکرمہ سے بھی مروی ہے.سعید حرث بن غیطلہ نام بتاتے ہیں اورعکرمہ حرث بن قیس.مگریہ اختلاف نہیں کیونکہ زہری کے نزدیک غیطلہ اس کی ماں کانام تھا اورقیس باپ کانام تھا.
Page 379
یہی آخری معنے ہیں.تفسیر.یقین کے معنے اس جگہ پر موت کے ہیں.فرماتا ہے کہ اب تو موت تک ہماری عبادت میں لگارہ یعنے اسلام کو جو ترقی ملے گی.اس میں اب کوئی رخنہ نہیں پڑے گا.اورتوبافراغت اپنی موت تک کھلے بندوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرسکے گا اوریہ لوگ اس وقت جوتیری عبادات میں روکیں ڈالتے ہیں.ان کو خدا تعالیٰ اس طرح مٹادے گاکہ تیری ساری زندگی عبادت کی آزادی کے لحاظ سے راحت میں گذرے گی.یقین کے معروف معنے بھی اس جگہ ہوسکتے ہیں اوراس صورت میں یہ معنے ہوں گے کہ جس ساعت کا وعدہ ہے اس کے آنے تک خاص طور پر عبادت میں مشغول رہوگویا عذاب یاساعتہ کے آثار ظاہر ہونے کانام یقین رکھا کیونکہ جب تک وعدہ پورانہ ہو اس کی پوری حقیقت ظاہر نہیں ہوتی.پس فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعد ہ ہوتو خاص طور پر دعااورعبادت میں لگ جانا چایئے تاکہ وہ وعدہ ہرقسم کی خیر کے ساتھ پوراہو.اس کے یہ معنے نہیں کہ دوسرے دنوں میں عبادت چھوڑ سکتاہے.کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت بھی رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے پس اس کے معنے معمول سے زیادہ عبادت اور توجہ کے ہیں.بعض نادا ن بدعتی اس آیت کے یہ معنے کرتے ہیں کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو عبادت فرض ہے جب یقین حاصل ہوجائے تو پھر نہیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ’’یقین کے حاصل ہونے تک عبادت کر ‘‘یہ نادان نہیں جانتے کہ اس طرح وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں.اورگویایہ کہتے ہیں کہ اس سورۃ کے اُترنے تک آپ کویقین کامل حاصل نہ ہواتھا.اگر محمد رسول اللہ( صلی اللہ علیہ وسلم) کو نبوت کے بعد یقین حاصل نہ ہواتھا تو ان ذلیل لوگوں کو یقین کس طرح حاصل ہو سکتا ہے نَعُوْذُ بِاللہِ مِنْ ھَذِہِ الْخُرَافَاتِ.ایک دفعہ میرے پاس ایک ایسا ہی شخص آیا اورسوال کیا کہ کشتی کاسوار جب کنا رہ پر پہنچے توکشتی ہی میں بیٹھارہے یااُتر آئے.میں نے کہا.کہ اگر دریا محدود ہے اورا س کاکنارہ ہے توکنارہ پر اُتر آئے لیکن اگر دریا بے کنارہے توجس کو وہ کنار ہ سمجھتا ہے وہ اس کی عقل کادھوکہ ہے اس لئے وہ جہاں اُترے گاوہیں ڈوبے گا.اس پر وہ سخت شر مندہ ہوا.