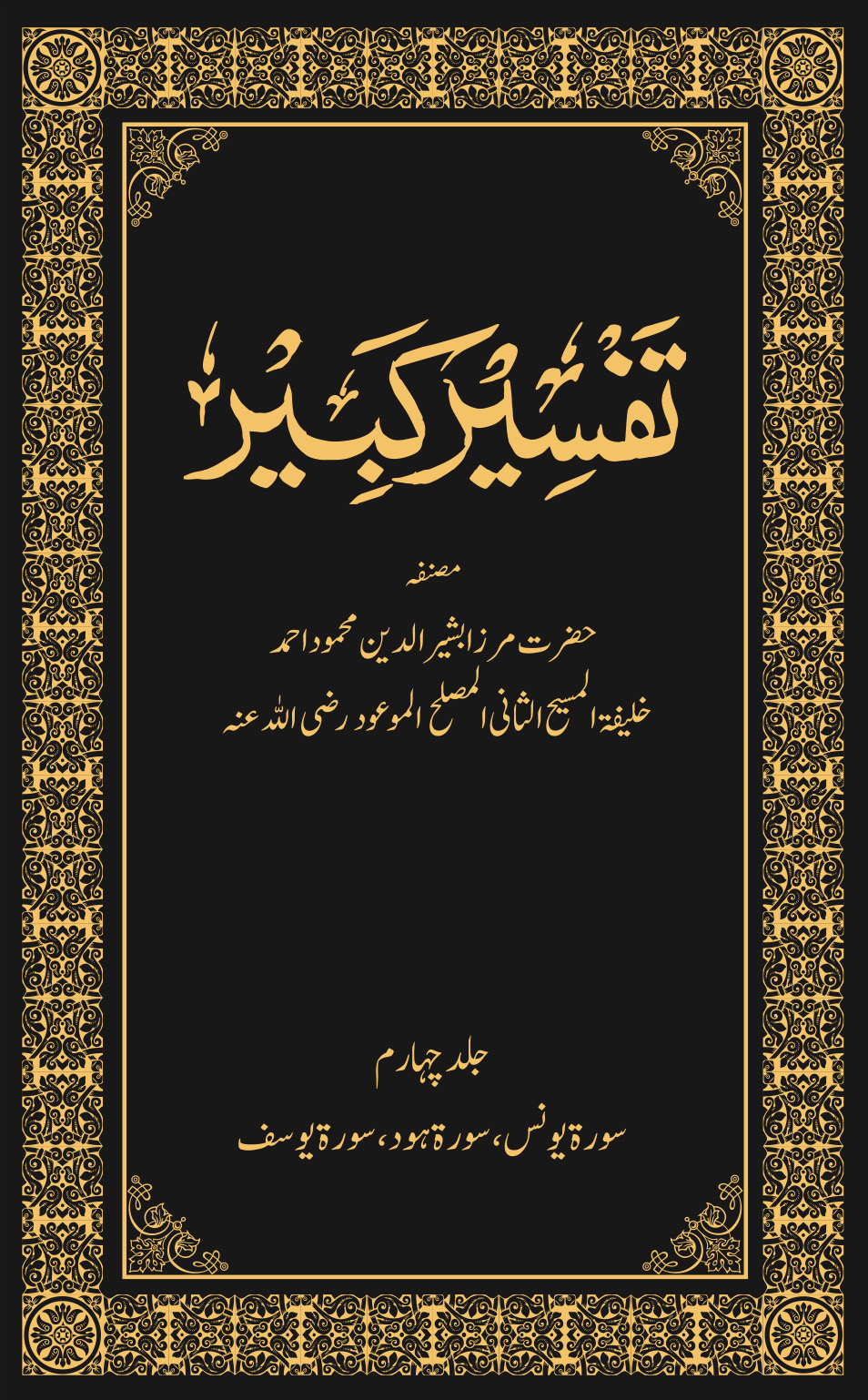Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 4
Content sourced fromAlislam.org
Page 9
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ استعاذہ کا حکم قرآن کریم میں حکم ہے کہ اس کے پڑھنے سے پہلے اعوذ پڑھ لینی چاہیے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (النحل : ۹۹) کہ جب تو قرآن پڑھنے لگے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرلیا کر یعنی ہر قسم کے شرور کے مقابلہ کے لئے خدا تعالیٰ کی مدد اور اس کی پناہ مانگ لیا کر.پناہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے.ایک پناہ ہوتی ہے اس بات سے کہ کوئی شر ہمیں نہ پہنچ جائے.اور ایک پناہ ہوتی ہے اس بات سے کہ کوئی خیر ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے.فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ کے حکم میں دونو قسم کی پناہ شامل ہے.یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے دل کی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بد صحبت کی وجہ سے یا کسی گناہ کی سزا کی وجہ سے یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے.یا یہ کہ اس تعلیم کے صحیح طور پر سمجھنے سے تم قاصر رہو.اور کوئی شر کا پہلو تمہارے لئے پیدا ہو جائے.اس استعاذہ کو عملی صورت دینے کے لئے جو دعا سکھلائی گئی ہے وہ اَعُوْذُبِاللہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ کی دعا ہے.تقدیم استعاذہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس حکم سے آخر میں اعوذ پڑھنے کا حکم نکلتا ہے نہ کہ شروع میں.چنانچہ قرآن کریم کے آخر میں ہی اعوذ کی دونو سورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس رکھی گئی ہیں.اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان آخر میں بھی اعوذ پڑھے تو اور بھی اچھی بات ہے مگر سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتداء
Page 10
میں اعوذ کا پڑھنا چونکہ ثابت ہے اس لئے اس حکم سے زیادہ تر قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھنا مراد لیا جائے گا.چنانچہ جبیر بن مطعمؓ سے بیہقی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے.اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ فِی الصَّلٰوۃِ کَبَّرَ ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِاللہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ(سنن الکبریٰ للبیہقی و المصّنف لابن شیبۃ کتاب الصلوٰۃ).یعنی تکبیر کے بعد تلاوت سے پہلے آپؐ اعوذ پڑھا کرتےتھے.ابوداؤد نے ابوسعیدؓ سے روایت کی ہے کہ نماز کی ابتدا میں تسبیح و تحمید کے بعد تلاوت سے پہلے آپؐ اعوذ پڑھتے تھے(ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب من رأی الاستفتاح بسبحانک ).ابوداؤد میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آیاتِ اِفک کی تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ پڑھا (ابو داؤدکتاب الصلوٰۃ و درمنثور تحت قولہ تعالٰی فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللّٰہ).الفاظ قرآنی بھی اس کے مخالف نہیں.کیونکہ قَرَأَ کے معنی پڑھنا شروع کرنے اور ختم کرنے دونوں کے ہوسکتے ہیں
Page 11
سُوْرَۃُ یُوْنُسَ مَکِّیَّۃٌ وَھِیَ مِائَۃٌ وَّتِسْعُ اٰیاتٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَاَحَدَ عَشَرَ رَکُوْعًا سورۃ یونس.یہ سورۃ مکی ہے.اور بسم اللہ سمیت اس کی ایک سو دس آیات ہیں اور گیارہ رکوع ہیں یہ سورۃ مکّی ہے (۱) یہ سورۃ مکّی ہے.گو بعض لوگوں نے اس کی بعض آیتوں کو مدنی قرار دیا ہے مگراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی رائے واقعات پر مبنی نہیں بلکہ صرف مضامین پر قیاس کرکے ہے اور اس قسم کی رائے یقینی نہیں ہوتی.وجہ تسمیہ (ب) اس سورۃ کا نام یونس ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نےخیال کیا ہے کہ اس میں حضرت یونس کا ذکر ہے.بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ کا مضمون یونس کے واقعہ پر مبنی ہے.قرآن کریم میں جو بعض انبیاء یا اشیاء کے ناموں پر سورتوں کا نام ہوتا ہے تو بلاوجہ نہیں ہوتا.بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس سورۃ کا مضمون اس خاص شخص کے مذکور واقعہ پر یا اس چیز کے حالات پر مبنی ہے جس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے.شمار آیات و رکوعات (ج) سورتوں کے شروع میں جو رکوعوں کی یا آیتوں کی تعداد دی جاتی ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رکوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں یا یہ کہ آیتوں کی تعداد آپ نے بتائی ہے.رکوع بہت بعد میں بنائے گئے ہیں اور آیات کی گنتی کے متعلق بھی اختلاف ہے اور اس کی بنیاد نحوی قواعد پر ہے.کسی شخص نے کسی مقام پر مضمون کو مکمل قرار دے لیا ہے اور کسی نے کسی جگہ پر.اور اس کی وجہ سے آیتوں کی تعداد میں ائمہ میں اختلاف ہو گیا ہے اور یہ اختلاف تین قسم کا ہے.بعض نے سورۃ کی آیتوں کی تعداد میں تو اتفاق کیا ہے مگر آیتوں کی حد بندی میں اختلاف کیا ہے یعنی جسے ایک نے دو آیتیں قرار دیا ہے دوسرے نے ایک قرار دے لیا ہے اور جسے دوسرے نے دو قرار دیا ہے اسے اس نے ایک قرار دے لیا ہے.دوسرا اختلاف یہ ہے کہ بعض نے بعض سورتوں کی آیتوں کی معروف تعداد سے کم تعداد بتائی ہے.اور تیسرا یہ اختلاف ہے کہ بعض جگہ بعض علماء نے آیتوں کی معروف تعداد سے زیادہ تعداد بتائی ہے.اس وجہ سے قرآن کریم کی کل آیات کے متعلق بھی اختلاف ہو گیا ہے.کوئی زیادہ آیتیں بتاتا ہے کوئی کم.تعداد آیات پر مسیحی مصنّفین کا اعتراض حقیقت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے بہت سے مسیحی مصنفوں نے یا دوسرے دشمنانِ اسلام نے اس امر کو قرآن کریم کے غیر محفوظ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے.مثلاً جنہوں نے آیتوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے ان کا حوالہ دے کر وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے اس
Page 12
قدر آیات ہوتی تھیں موجودہ قرآن میں اس قدر لکھی ہیں.معلوم ہوا کہ اس قدر آیات کم ہو گئی ہیں.یا کم والی روایت کو لے کر کہہ دیا کہ موجودہ قرآن میں اس قدر آیات ہیں.پہلے بزرگوں نے اس قدر لکھی ہیں معلوم ہوا کچھ آیتیں زائد ہو گئی ہیں.حالانکہ یہ صریح دھوکا اور غلط بیانی ہے.جو لوگ آیتوں کی تعداد زیادہ بتاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ مضمون موجودہ مضمون سے زیادہ تھا بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں حصہ آیت کو جو ایک آیت قرار دیا گیا ہے اسے ایک آیت نہ سمجھو.اور جو کم کہتے ہیں وہ بھی اسی بنا پر کہتے ہیں.کہ فلاں فلاں آیتوں کو جو تم دو آیتیں بناتے ہو ان کو دو آیتیں نہ سمجھو.ایک ہی آیت سمجھو لیکن وہ یہ ہرگز نہیں کہتے کہ اصل میں قرآن کریم کا مضمون تھوڑا تھا اور اب زیادہ کر دیا گیا ہے.مثلاً سورہ فاتحہ ہے.بعض اسے آٹھ آیتیں قرار دیتے ہیں اور بعض سات.آٹھ کہنے والے کوئی اور آیت شامل نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الگ آیت ہے.اور الحمدللہ سے سات آیتیں گناتے ہیں.اور بسم اللہ کو ملا کر آٹھ قرار دیتے ہیں.بعض اور ہیں جو بسم اللہ کو پوری آیت نہیں قرار دیتے بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے ملا کر ایک آیت قرار دیتے ہیں.پس باوجود آیتوں کی تعداد میں اختلاف کے مسلمانوں میں قرآن کریم کے مضمون کے متعلق اختلاف نہیں ہے.اور یہ کوئی بھی نہیںکہتا کہ موجودہ قرآن کریم میں کوئی ٹکڑا ایسا ہے جو قرآن کریم کا جزو نہیں ہے.اور کسی نے ملا دیا ہے.پس تعداد کا اختلاف کچھ حقیقت نہیں رکھتا.یہ ایک ذوقی اختلاف ہےاور اس سے دشمنانِ اسلام کا فائدہ اٹھانا خود ان کی اپنی بے وقوفی پر دلالت کرتا ہے.ترتیب سُوَر اور ان کا باہم تعلق مضمون دیگر مطالب کے بیان کرنے سے پہلے میں اس تعلق کی نسبت کچھ کہنا چاہتا ہوں جو سورۂ یونس اور اس کے بعد کی سورتوں کو ان سے پہلی سورتوں کے ساتھ ہے.میں نے جہاں تک غور کیا ہے قرآن کریم میں نہ صرف ہر آیت کو دوسری آیت کے مضمون کے ساتھ رابطہ ہے بلکہ ہر سورہ اپنے سے پہلی اور پچھلی سورتوں کے مضمون سے وابستہ ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کمال ہے کہ بعض سورتوں کے مجموعوں کا دوسری سورتوں کے مجموعوں سے بھی تعلق ہے اور اس طرح ایک زبردست اتصال ہے جو سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر سورۃ الناس کی آیت مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ تک پایا جاتا ہے.دشمن کہتا ہے کہ قرآن کریم بے ترتیب ہے.لیکن حق یہ ہے کہ نہ صرف قرآن کریم کے مضمون میں ایک مکمل ترتیب ہے بلکہ قرآن کریم کی سورتیں ایک سے زیادہ طریق سے باہم وابستہ ہیں.اور ان کی ترتیب کو دیکھ کر قرآن کریم کے معجزانہ کلام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں رہ جاتا.اس مضمون کی طرف اس جگہ توجہ دلانے کی یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے پہلے دس پاروں کے نوٹ بعد میں شائع کرنے پڑے ہیں.پس ضرورت تھی کہ اس جگہ اس مضمون کے متعلق ایک مختصر نوٹ دے دیا جاتا تاکہ پڑھنے
Page 13
والوں کے ذہن میں خلش باقی نہ رہ جائے.پہلی سورتوں سے تعلق یاد رکھنا چاہیے کہ سورۂ یونس کو پہلی سورۃ کے مضمون سے تین تعلق ہیں.اول اس سورۃ کا تسلسل پہلی سورۃ سے جو یہ ہے کہ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو مضامین کا ذکر فرمایا تھا.(۱) وَ اِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ١ؕ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا١ؕ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ(التوبۃ :۱۲۷)یعنی جب کوئی سورۃ اترتی ہے تو ان (منافقوں) میں سے بعض دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں (یہ اشارہ کرتے ہوئے) کہ کیا کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں پھر اٹھ کر (مجلس سے) چلے جاتے ہیں.خدا بھی ان کے دلوں کو حق سے محروم کر دے گا.(۲)لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (التوبۃ:۱۲۸) یقیناً تمہارے پاس تمہی میں سے ایک ایسا رسول آچکا ہے جس پر تمہارا مصائب میں مبتلا ہونا شاق گزرتا ہے.غرض سورہ توبہ کے اختتام پر پہلے کتاب کے نزول اور اس کی تکذیب کا اور پھر رسول کی آمد اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ذکر تھا.اسی طرح سورہ یونس کے ابتداء میں انہی دونو امور کا اس ترتیب سے ذکر شروع کیا ہے کہ پہلے کتاب کی اہمیت بتائی کہ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ(یونس:۲) اور پھر رسول کا ذکر فرمایااَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ(یونس:۳).دوسرا تعلق سورہ یونس کا سورہ توبہ سے یہ ہے کہ سورہ یونس کا مضمون پورے طور پر سورہ توبہ کے مضمون کو مکمل کرتا ہے.اور وہ اس طرح کہ سورۂ توبہ میں جو دراصل الگ سورۃ نہیں ہے بلکہ سورۂ انفال کا حصہ ہے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اب اسلام کی ترقی کا وقت آ گیا ہے اور خدا تعالیٰ کے وعدے بڑے زور شور سے پورے ہونے لگے ہیں پس چاہیے کہ لوگ اپنے دلوں کی صفائی کرکے خدا تعالیٰ کے حضور میں جھک جائیں.تا ان کی توبہ قبول ہو.چونکہ بعض لوگوں کے دلوں میں کثرت گناہ کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید ہماری توبہ بھی اب قبول نہ ہوسکے.اس لئے سورۂ یونس میں اس مضمون پر بحث کی کہ اللہ تعالیٰ کا رحم غالب ہے.وہ ہر صورت میں بندے پر رحم کرتا ہے.ہاں !اسے کامل توبہ کا نمونہ دکھانا چاہیے.تیسرا تعلق سورہ یونس کو پہلی تمام سورتوں سے یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک آٹھ یا ہماری تحقیق کے مطابق سات سورتیں ہیں (سورۂ توبہ الگ سورۃ نہیں بلکہ سورہ انفال کا حصہ ہے اور بوجہ عظمت مضمون کے الگ لکھوائی گئی ہے) ان سورتوں کا مضمون ایک قسم کا ہے.اس کے بعد سورۂ یونس سے لے کر سورۂ کہف تک ایک سلسلہ مضمون کا ہے اور یہ دونوں سلسلے مضمون کے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں.پہلی آٹھ سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پیش کرکے اور آپ کے کام کو دکھا کر اسلام کی صداقت کو ثابت کیا گیا ہے.اور اسلام کے
Page 14
پیش کردہ عقائد کی برتری اور اس کی تعلیم کی خوبی اور اس کے وسیع عرفان اور اس کی تعلیم کی حکمتوں اور اس کے غیر معمولی نیک اثر کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے مگر سورہ یونس اور اس کے ساتھ کی سورتوں میں دلائل عقلیہ اور منہاج نبوت پر اور پہلے انبیاء کے دعووں اور ان کے حالات کی طرف توجہ دلا کر نبوت اور اس کی ضرورت، مذہب اور اس کی اہمیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے اغراض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.پس سلسلہ مضمون ایک ہی ہے.صرف فرق یہ ہے کہ پہلے سلسلے میں ان پیشگوئیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یا اس سے پہلے دیگر انبیاء کی طرف سے کروائی گئی تھیں اور وقت پر پوری ہوئیں.اور دوسرے سلسلہ میں اصولی رنگ میں اور منہاج نبوت کے ذریعہ سے اسلام کو پیش کیا گیا ہے.بعض مدنی سورتیں بعض مکی سورتوں سے پہلے کیوں رکھی گئیںہیں یاد رکھنا چاہیے کہ پہلا سلسلہ سورتوں کا مدنی ہے.ان میں سے صرف دو مکی ہیں.یعنی سورہ انعام اور سورۂ اعراف.لیکن یہ سورتیں ہجرت کے بالکل قریب نازل ہوئی ہیں.اور اس وجہ سے مدنی سورتوں کی طرح ہی سمجھنی چاہئیں.سورہ یونس اور اس کے ساتھ کی سورتیں سب کی سب مکی ہیں.اور ان میں سے بعض وسطی زمانہ کی اور بعض ہجرت کے قریب کی ہیں.پس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ان مدنی سورتوں کو پہلے کیوں رکھا گیا ہے.اور مکی سورتوں کو بعد میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر پہلی سورتوں کو مضمون کے لحاظ سے پہلے ہی پڑھنا مناسب تھا تو کیوں خدا تعالیٰ نے ان کو پہلے نازل نہ کیا ؟اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کام حکمت سے پُر ہوتا ہے.چونکہ نبی کے پہلے مخاطبوں اور بعد میں آنے والوں کی ضرورتوں میں فرق ہوتا ہے.اس لئے قرآن کریم کے نزول کی ترتیب اور تحریر کی ترتیب میں فرق رکھا گیا ہے.نزول کی ترتیب ان لوگوں کے حالات کو مدنظر رکھ کر ہے جو قرآن کریم کے پہلے مخاطب تھے اور جمع کی ترتیب ان لوگوں کو مدنظر رکھ کر ہے جو بعد میں آنے والے تھے.اب یہ امر ظاہر ہے کہ جب کوئی تشریعی نبی دعویٰ کرے گا تو اس وقت اس کی تعلیم یا اس کی پیش گوئیوں کا پورا ہونا زیربحث نہیں ہوگا.کیونکہ نہ تو شروع میں تعلیم مکمل صورت میں لوگوں کے سامنے ہو گی نہ ابھی پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا وقت آیا ہوگا.پس شروع زمانہ میں لوگ ان امور پر بحث نہیں کریں گے.بلکہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بحث اس امر پر ہوگی کہ وہ کیسا خدا ہے جس کی طرف سے ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے.اس کی کیا صفات ہیں.اس کی کیا طاقتیں ہیں.کیا الہام کوئی حقیقت رکھتا ہے.انسان کو الہام کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس قسم کے اور سوالات ہوں گے جن کی طرف لوگ توجہ کریں گے.پس کلام الٰہی لازماً انہی امور
Page 15
پر مشتمل ہوگا جن کی طرف اس زمانہ کے لوگوں نے توجہ کرنی ہے اور نیز پیش گوئیوں پر جو آئندہ اس کے صدق دعویٰ پر دلیل ہوں اسی طرح شریعت کے بعض ابتدائی مسائل بتائے جائیں گے.(۲) دوسرا زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس کے دعویٰ کی حقیقت کو سمجھ کر اس کی مخالفت پر آمادہ ہوں گے اور اس کی آمد کو عبث قرار دیں گےاور اس کے عقائد جو وہ خدا تعالیٰ کے متعلق یا ایک مذہبی نظام کے متعلق بیان کرتا ہو اسے ردّ کریں گے اور کچھ لوگ مان بھی لیں گے.اس وقت اس امر کی ضرورت ہو گی کہ اس کی آمد کی غرض کو بتایا جائے اور پہلی تاریخ کی شہادت سے اس کے دعویٰ کو سنۃ اللہ کے مطابق بتایا جائے.اور عام عقلی دلائل اس کے دعویٰ کی تائید میں بتائے جائیں.اور پہلے انبیاء کے حالات سے سبق لینے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے اور شریعت کی بعض تفصیلات بتائی جائیں اور ماننے والوں کو ان کے فرائض سے اور کامیابی کے لئے جدوجہد کے اصول سے آگاہ کیا جائے.(۳) پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ وہ ہوگا کہ اس میں شریعت مکمل کرکے اس کو بطور حجت کے پیش کیا جائےاور جو پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہوں ان کو پیش کرکے مخالفین کو قائل کیا جائے.غرض خود اس نبی کے اپنے کام پیش کرکے بتایا جائے کہ یہ سچا ہے جھوٹا نہیں.اور جو کام کرچکا ہے وہی اس امر کا ثبوت ہے کہ اسے ماننے میں دنیا کی بہتری ہے.لیکن پہلے زمانہ کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ مذہب سے ایسے ناواقف نہ ہوں گے جیسے کہ پہلے زمانہ کے لوگ.ان کے سامنے ایک قائم شدہ جماعت ہو گی.جس کے دعویٰ سے ایک حد تک وہ واقف ہوں گے ان کے سامنے سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ اس مدعی کے دعویٰ کو کیوں تسلیم کیا جائے اس کی تعلیم دوسری تعلیموں کے مقابلہ میں کیوں قابلِ قبول ہے اور اس کے کیا کام ہیں؟ جب ان امور کو سمجھ کر کوئی شخص مذہب کی حقانیت کو سمجھ جائے گا تو دوسرے نمبر پر علم کی زیادتی کے لئے اسے یہ ضرورت ہو گی کہ منہاج نبوت کی بناء پر اصولی رنگ میں بھی وہ صداقت کو سمجھ لے اور اس کے بعد پھر دوسرے امور کی طرف اس کی توجہ پھرے گی.پس اس طبعی تقاضا کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کے نزول کی ترتیب اور ہے اور اس کے جمع کی ترتیب اور.نزول کی ترتیب پہلے زمانہ کے لوگوں کی ضرورت کو مدنظر رکھ کر ہے اور جمع کی ترتیب بعد میں آنے والوں کی ضرورت کو مدنظر رکھ کر ہے.اور یہ بات خود ایک ایسی بیّن فضیلت ہے جو صاحب بصیرت کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے.
Page 16
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر( شروع کرتا ہوں) جو بے حد کرم کرنے والا( اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.بسم اللہ کے متعلق حضرت موسیٰ ؑ کی ایک پیشگوئی یہ آیت جو ہر سورت کے پہلے آتی ہے ایک پیشگوئی کو یاد دلاتی ہے.وہ پیشگوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے اور کتاب استثنا باب ۱۸ آیت۱۹ میں بیان کی گئی ہے.اور اس کی تفصیل کتاب خروج باب ۱۹، ۲۰ میں مذکور ہے خروج میں لکھا ہے کہ خدا تعا لیٰ نے حضرت موسیٰ ؑسے کہا کہ بنی اسرائیل کو پاک کر کے سینا کے نیچے لا کھڑا کر.تاکہ وہ سنیں کہ میں تجھ سے کلام کر تا ہوں پہلے تو وہ پہاڑ کے پاس کھڑے رہیں.لیکن جب قرناء کی آواز بہت بلند ہو تو ادھر آجائیں حضر ت موسیٰ ؑجب وہاں گئے اور خدا کا کلام نازل ہوا تو ساتھ اس کے بجلی چمکی اور دھواں اٹھااور گرج ہوئی.تو لوگ ڈر کر دور کھڑے ہوگئے.جب موسیٰ ان کے پاس واپس گئے تو انہوں نے انہیں کہا.کہ ’’ تو ہی ہم سے بول اور ہم سنیں لیکن خدا ہم سے نہ بولے کہیں ہم مر نہ جائیں‘‘.موسیٰ ؑنے لوگوں کو کہا کہ تم مت ڈرو.اس لئے کہ خدا آیا ہے کہ تمہیں امتحان کرے.اور تاکہ اس کا خوف تمہارے سامنے ظاہر ہو کہ تم گناہ نہ کرو.تب وے لوگ دور ہی کھڑے رہے.اور موسیٰ ؑکالی بدلی کے جس میں خدا تھا نزدیک گیا.(خروج باب ۲۰ آیت ۱۹تا ۲۱)حضرت موسیٰ ؑنے خدا سے جاکر عرض کی کہ الٰہی میری قوم تو تیرے پاس نہیں آتی.تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی ’’انہوں نے جو کچھ کہا سو اچھا کہا.میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ ساایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا.اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا.اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا.(استثنا باب ۱۸ آیت ۱۸) اس پیشگوئی میں بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی ان کا مثیل ہو کر آئے گا.اوروہ جب خدا کا کلام سنائے گا تو کہے گا کہ میں خدا کا نام لے کر یہ کلام سنا تا ہوں.’’خدا کا نام لے کر ‘‘ سناتا ہوں کا ترجمہ عربی زبان میں بسم اللہ ہے.پس بسم اللہ ہر یہودی اور عیسائی کو توجہ دلاتی ہے کہ اگر تم اس کتاب کو رد کرو گے تو موسیٰ ؑ کی پیشگوئی کے بموجب پکڑے جاؤ گے.اتنے واضح لفظوں میں یہ پیشگوئی تھی.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسے نہ یہودیوں نے سمجھا نہ عیسائیوں نے.یہاں تک کہ قرآن کریم میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نازل ہوئی.تب پتہ لگا کہ اس کا مفہوم کیا تھا ؟موسیٰ کی پیشگوئی کے الفاط ’’ اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جو وہ میرا نام لے کے کہے گا
Page 17
نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا‘‘ صاف بتا تے ہیں کہ بِسْمِ اللّٰہِ کے الفاظ اس کے ہر نئے کلام کے پہلے ہوں گے.پس بِسْمِ اللّٰہِ کا ہر سورۃ سے پہلے آنا اس پیشگوئی کے مطابق ہے.اور اس پر تکرار کا اعترنہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لواض خصوصاً ان اقوام کے منہ سے جو موسیٰ ؑ کی پیرو ہیں بالکل زیب نہیں دیتا.کیا بسم اللہ پہلی کتب سے لی گئی ہے مسیحیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ آیت پہلی کتب سے نقل کی گئی ہے.راڈول لکھتا ہے کہ یہ کلمہ یہودی الاصل ہے (تفسیر القرآن از ویری صفحہ ۲۸۶) ویری لکھتا ہے کہ ’’یہ امر قریباً یقینی ہے کہ یہ کلمہ محمد (صلعم) نے یہودیوں اور صابیوں سے مستعار لیا ہے.آخرالذکر ہمیشہ اپنی تحریروں سے پہلے یہ لکھا کرتے تھے ’’بنام یزداں بخشائش گر داد گر‘‘ (تفسیر القرآن از ویری صفحہ ۲۸۹) پادری سنٹ کلیرٹسڈل صاحب نے اپنی کتاب ینابیع الاسلام میں اس عبارت کو زردشتیوں کی طرف منسوب کیا ہے اور لکھا ہے کہ کتاب دساتیر میں ہر نبی کے صحیفے سے پہلے یہ عبارت ہے کہ بنام ایزد بخشائش گر مہربان دادگر (اردو ترجمہ ینابیع الاسلام صفحہ ۱۲۷) اب یہ عجیب بات ہے کہ تین مسیحی مصنّف اس آیت کو مسروقہ ثابت کرنے کے لئے تین سرچشمے اس کے بیان کرتے ہیں.ایک یہودیوں کو اس کا سرچشمہ بناتا ہے دوسرا صابیوں کو، تیسرا زردشتیوں کو.اس قدر کوشش ان لوگوں کی اس آیت کو مسروقہ ثابت کرنے کی بتاتی ہے کہ اس آیت کی عظمت کے تو یہ لوگ بھی قائل ہیں ورنہ صرف اس قدر لکھ دیتے کہ اس آیت کے مضمون میں کوئی خاص بات نہیں ہے.پھر سوال یہ ہے کہ تینوں سرچشموں میں سے اصل سرچشمہ کون سا ہے.جب تین سرچشمے ہیں تو ان میں سے کون سے چور ہیں اور کون سا اصلی ہے.آیا یہودیوں نے زردشتیوں یا صابیوں سے چرایا ہے یا برعکس معاملہ ہے؟ سب سے بڑھ کر لطیفہ یہ ہے کہ یہودیوں میں اس کلمہ کے استعمال کا ایک بھی حوالہ نہیں دیا گیا اور نہ وہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ جن میں یہودی اس آیۃ کو استعمال کرتے تھے بلکہ باوجود اس کے کہ مسیحیت یہودیت کی شاخ ہے اور یہودی کتب گویا مسیحیوں کی اپنی مذہبی کتب ہیں پھر بھی مسیحی مصنف یہودی کتب کا تو حوالہ نہیں دے سکے اور نہ ان کے الفاظ نقل کرسکے.لیکن زردشتیوں اور صابیوں کی کتب کے حوالے انہوں نے نقل کر دیئے ہیں.مگر یہ حوالے خود مشکوک ہیں.کیونکہ زردشتی ان کتب کو وضعی قرار دیتے ہیں.اور کوئی تعجب نہیں کہ وہ سب یا ان کے بعض حصے اسلام کے بعد بنائے گئے ہوں.لیکن اگر انہیں صحیح بھی تسلیم کرلیا جائے تب بھی قرآن کریم پر کوئی اعتراض نہیں ہے.کیونکہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ یہ آیت پہلی دفعہ قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے بلکہ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے بھی
Page 18
دنیا میں موجود تھی.چنانچہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جو خط ملکۂ سبا کو لکھا تھا اس میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بھی درج تھا.پس اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہود یا زردشتیوں یا صابیوں یا کسی اور قوم میں یہ آیت پہلے سے موجود تھی تو بھی کوئی حرج نہیں.کیونکہ قرآن کریم خود تسلیم کرتا ہے کہ یہ آیت حضرت سلیمان کو معلوم تھی اور جو آیت حضرت سلیمان کو معلوم تھی وہ اور انبیاء اور ان کے متبعین کو بھی معلوم ہوسکتی ہے.صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ آیت عربی میں نازل ہوئی اور پہلی قوموں میں ان کی اپنی زبانوں میں مگر باایں ہمہ قرآن کریم میں اس آیت کی موجودگی نقل نہیں کہلاسکتی.کیونکہ قرآن کریم میں اس آیت کا وجود ایک پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے ہے.اور جو کلام کسی نئی غرض کے لئے دوہرایا جائے اور کسی خاص فائدہ کے لئے لایا جائے وہ نقل یا چوری ہرگز نہیں کہلاتا.موسیٰ ؑ کی پیشگوئی تھی کہ (۱) بنی اسمٰعیل میں سے ایک نبی آئے گا.(۲) اس کو موسیٰ کی طرح شریعت دی جائے گی (۳) وہ جو نیا مضمون بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے پاکر دنیا کے سامنے پیش کرے گا اس سے پہلے یہ کہہ لے گا کہ میں خدا تعالیٰ کا نام لے کر اس کلام کو شروع کرتا ہوں.(۴) اگر کوئی جھوٹا انسان اس پیشگوئی کو اپنے پر چسپاں کرنا چاہے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا.(۵) اور جو اس پیشگوئی کے مصداق کا انکار کرے گا وہ بھی ہلاک کیا جائے گا.اب بتاؤ اس پیشگوئی کا مصداق سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سوائے قرآن کریم کے اور کون ہے؟ پس قرآن کریم میں ہر سورت سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے ہے.مگر کیا یہ امردساتیر کے متعلق ثابت کیا جاسکتا ہے.کیا ان کے مصنف بنی اسمٰعیل میں سے تھے.یا موسیٰ کی طرح شریعت لائے تھے یا ان کی وحی سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ لکھا ہوا ہوتا تھا؟ وہ تو ایک تاریخ کی کتاب ہے جس میں انبیاء کا حال ہے.اور موسیٰ کی پیشگوئی میں یہ شرط ہے کہ اس نبی کے ہر مستقل حصۂ وحی سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ ہو.غرض باوجود اس کے کہبِسْمِ اللّٰهِ پہلے انبیاء کی امتوں میں مروج تھی.قرآن کریم میں اس کا وجود تکرار یا چوری نہیں کہلاسکتا.کیونکہ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ اس سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ تھی اور اس لئے کہ اس میں بِسْمِ اللّٰهِ موسیٰ ؑ کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے آئی ہے.اور اگر ایسا نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی جھوٹی جاتی.الٓرٰ١۫ مقطّعات قرآن کریم حروف مقطّعات اپنے اندر بہت سے راز رکھتے ہیں.ان میں سے بعض راز بعض
Page 19
ایسے افراد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کا قرآن کریم سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں ہونا چاہیے.لیکن اس کے علاوہ یہ الفاظ قرآن کریم کے بعض مضامین کے لئے قفل کا بھی کام دیتے ہیں.کوئی پہلے ان کو کھولے تب ان مضامین تک پہنچ سکتا ہے.جس جس حد تک ان کے معنوں کو سمجھتا جائے اسی حد تک قرآن کریم کا مطلب کھلتا جائے گا.مقطّعات میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے میری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب حروف مقطعات بدلتے ہیں تو مضمون قرآن جدید ہو جاتا ہے اور جب کسی سورت کے پہلے حروف مقطعات استعمال کئے جاتے ہیں تو جس قدر سورتیں اس کے بعد ایسی آتی ہیں جن کے پہلے مقطعات نہیں ہوتے ان میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے.اسی طرح جن سورتوں میں وہی حروف مقطعات دہرائے جاتے ہیں وہ ساری سورتیں مضمون کے لحاظ سے ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی ہوتی ہیں.الٓمّٓ سے شروع ہونے والی سورتیں میں بتا چکا ہوں کہ میری تحقیق میں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ توبہ تک ایک ہی مضمون ہے.یہ سب سورتیں الٓمّٓ سے تعلق رکھتی ہیں.سورۂ بقرہ الٓمّٓ سے شروع ہوتی ہے.پھر سورئہ آل عمران بھی الٓمّٓ سے شروع ہوتی ہے.پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ انعام حروفِ مقطعات سے خالی ہیں.اور اس طرح گویا پہلی سورتوں کے تابع ہیں.جن کی ابتداء الٓمّٓ سے ہوئی ہے.ان کے بعد سورۂ اعراف الٓمّصٓ سے شروع ہوتی ہے اس میں بھی وہی الٓمّٓ موجود ہے.ہاں حرف ص کی زیادتی ہوئی ہے.اس کے بعد سورہ انفال اور براءہ حروف مقطعات سے خالی ہیں.پس سورۂ براءۃ تک الٓمکا مضمون چلتا ہے.سورہ اعراف میں جو ص بڑھایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرف تصدیق کی طرف لے جاتا ہے.سورہ اعراف انفال اور توبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور اسلام کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے.سورۂ اعراف میں اصولی طور پر اور انفال اور توبہ میں تفصیلی طور پر تصدیق کی بحث ہے اس لئے وہاں صٓ کو بڑھادیا گیا ہے.الٓرٰسے شروع ہونے والی سورتیں سورہ یونس سے الٓمّٓ کی بجائے الٓرٰ شروع ہو گیا ہے.الٓ تو وہی رہا اور مٓ کو بدل کر رٰ کر دیا.پس یہاں مضمون بدل گیا.اور فرق یہ ہوا کہ بقرہ سے لے کر توبہ تک تو علمی نقطہ نگاہ سے بحث کی گئی تھی اور سورۂ یونس سے لے کر سورہ کہف تک واقعات کی بحث کی گئی ہے.اور واقعات کے نتائج پر بحث کو منحصر رکھا گیا ہے.اس لئے فرمایا کہ الٓرٰ یعنی انااللہ ارٰی.میں اللہ ہوں جو سب کچھ دیکھتا ہوں.اور تمام دنیا کی تاریخوں پر نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو تمہارے سامنے رکھتا ہوں.غرض ان سورتوں میں رؤیت کی صفت پر زیادہ بحث کی گئی ہے اور پہلی سورتوں میں علم کی صفت پر زیادہ بحث تھی.
Page 20
مقطعات بے معنی نہیں ہوتے میں فی الحال اس جگہ اختصاراً اتنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حروف مقطعات کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بے معنی ہیں اور انہیں یونہی رکھ دیا گیا ہے.مگر ان لوگوں کی تردید خود حروفِ مقطعات ہی کر رہے ہیں.چنانچہ جب ہم تمام قرآن پر ایک نظر ڈال کر یہ کہتے ہیں کہ کہاں کہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں تو ان میں ایک ترتیب نظر آتی ہے.سورہ بقرہ الٓمّٓ سے شروع ہوتی ہے.پھر سورۂ آل عمران الٓمّٓ سے شروع ہوتی ہے.پھر سورۂ نساء، سورۂ مائدہ، سورۂ انعام حروف مقطعات سے خالی ہیں پھر سورۂ اعراف الٓمّٓصٓ سے شروع ہوتی ہے.اور سورہ انفال اور براءۃ خالی ہیں.ان کے بعد سورۂ یونس، سورۂ ہود، سورۂ یوسف الٓرٰسے شروع ہوتی ہیں.اور سورۂ رعد میں م بڑھا کر الٓمٓرٰ کر دیا گیا ہے.لیکن جہاں الٓمّٓصٓ میں صٓ آخر میں رکھا یہاں مٓ کو رٰ سے پہلے رکھا گیا ہے.حالانکہ اگر کسی مقصد کو مدنظر رکھے بغیر زیادتی کی جاتی تو چاہیے تھا کہ میم کو جو زائد کیا گیا تھا راء کے بعد رکھا جاتا.میم کو الٓرٰ کے درمیان رکھ دینا بتاتا ہے کہ ان حروف کے کوئی خاص معنی ہیں.اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے الٓمّٓ کی سورتیں ہیں اور اس کے بعد الٓرٰ کی تو صاف طور پر معلوم ہوجاتا ہے کہ مضمون کے لحاظ سے میم کو راء پر تقدم حاصل ہے.اور سورۂ رعد میں میم اور راء جب اکٹھے کر دیئے گئے ہیں تو میم کو راء سے پہلے رکھنا اس امر کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ سب حروف خاص معنی رکھتے ہیں.اسی وجہ سے ان حروف کو جو معناً تقدم رکھتے ہیں ہمیشہ مقدم ہی رکھا جاتا ہے.سورۂ رعد کے بعد ابراہیم اور حجر میں الٓرٰ استعمال کیا گیا ہے.لیکن نحل بنی اسرائیل اور کہف میں مقطعات استعمال نہیں ہوئے.اور یہ سورتیں گویا پہلی سورتوں کے مضامین کے تابع ہیں.ان کے بعد سورۂ مریم ہے جس میں کٓہٰیٰعٓصٓ کے حروف استعمال کئے گئے ہیں.سورۂ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے اور اس میں طٰہٰ کے حروف استعمال کئے گئے ہیں.اس کے بعد انبیاء، حج، مومنون، نور اور فرقان میں حروف مقطعات چھوڑ دیئے گئے ہیں.گویا یہ سورتیں طٰہٰ کے تابع ہیں.آگے سورۂ شعراء طٰسٓمٓ سے شروع کی گئی ہے گویا طاء کو قائم رکھا گیا ہے اور ھاء کی جگہ س اور میم لائے گئے ہیں.اس کے بعد سورۂ نمل ہے.جو طٰسٓ سے شروع ہوتی ہے.اس میں سے میم کو اڑا دیا گیا ہے.اور طاء اور س قائم رکھے گئے ہیں.اس کے بعد سورہ قصص کی ابتداء پھر طٰسٓمٓ سے کی گئی ہے.گویا میم کے مضمون کو پھر شامل کر لیا گیا ہے.اس کے بعد سورۂ عنکبوت کو پھر الٓمّٓ سے شروع کیا گیا ہے اور دوبارہ علم الٰہی کے مضمون کو نئے پیرایہ اور نئی ضرورت کے ماتحت شروع کیا گیا ہے.(اگرچہ میں ترتیب پر اس وقت بحث نہیں کررہا لیکن اگر کوئی کہے کہ الٓمّٓ دوبارہ کیوں لایا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے الٓمّٓ کے مخاطب کفار تھے اور یہاں سے الٓمّٓ کے مخاطب مومن ہیں) سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم، سورہ لقمان اور
Page 21
سورہ سجدہ کو بھی الٓمّٓ سے شروع کیا گیا ہے.ان کے بعد سورہ احزاب، سبا، فاطر بغیر مقطعات کے ہیں.اور گویا پہلی سورتوں کے تابع ہیں.ان کے بعد سورہ یٰسٓ ہے.جس کو یٰسٓ کے حروف سے شروع کیا گیا ہے.اس کے بعد سورہ صافات بغیر مقطعات کے ہے.اس کے بعد سورہ صٓ حرف صٓ سے شروع کی گئی ہے.پھر سورۂ زمر حروف مقطعات سے خالی اور پہلی سورت کے تابع ہے.اس کے بعد سورہ مومن حٰمٓ سے شروع کی گئی ہے.اس کے بعد سورہ حم سجدہ کو بھی حٰمٓ سے شروع کیا گیا ہے.پھر سورہ شوریٰ کو بھی حٰمٓ سے شروع کیا گیا ہے لیکن ساتھ حروف عٓسٓقٓ بڑھائے گئے ہیں.اس کے بعد سورۂ زخرف ہے اس میں بھی حٰمٓ کے حروف ہی استعمال کئے گئے ہیں.پھر سورہ دخان، جاثیہ اور احقاف بھی حٰمٓ سے شروع ہوتی ہیں.ان کے بعد سورہ محمد، فتح اور حجرات بغیر مقطعات کے ہیں اور پہلی سورتوں کے تابع ہیں.سورہ قٓ صرف ق سے شروع ہوتی ہے.اور قرآن کریم کے آخر تک ایک ہی مضمون چلا جاتا ہے.یہ ترتیب بتارہی ہے کہ یہ حروف یونہی نہیں رکھے گئے.پہلے الٓمّٓ آتا ہے.پھر الٓمّٓصٓ آتا ہے.جس میں صٓ کی زیادتی کی جاتی ہے.پھر الٓرٰ آتا ہے اور پھر الٓمّٓرٰ آتا ہے کہ جس میں میم کی زیادتی کی جاتی ہے پھرکٓہٰیٰعٓصٓ آتا ہےجس میں ص پر چار اور حروف کی زیادتی ہے.پھر طٰہٰ لایا جاتا ہے اور پھر اس میں کچھ تبدیلی کرکے طٰسٓمٓ کر دیا جاتا ہے.یہ ایک ہی قسم کے الفاظ کا متواتر لانا اور بعض کو بعض جگہ بدل دینا بعض جگہ اور رکھ دینا بتاتا ہے کہ خواہ یہ حروف کسی کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں جس نے انہیں رکھا ہے کسی مطلب کے لئے ہی رکھا ہے.اگر یونہی رکھے جاتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کہیں ان کو بدل دیا جاتا، کہیں زائد کر دیا جاتا، کہیں کم کر دیا جاتا.مقطّعات کی دلالت کا اعتراف مخالفین اسلام کی طرف سے علاوہ مذکورہ بالا دلائل کے خود مخالفین اسلام کے ہی ایک استدلال سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ مقطعات کچھ معنی رکھتے ہیں.مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب ان کی لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے ہے.اب اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ عجیب بات نہیں کہ باوجود اس کے کہ سورتیں اپنی لمبائی اور چھوٹائی کے سبب سے آگے پیچھے رکھی گئی ہیں.ایک قسم کے حروف مقطعات اکٹھے آتے ہیں.الٓمّٓ کی سورتیں اکٹھی آگئی ہیں.الٓرٰ کی اکٹھی.طٰہٰ اور اس کے مشترکات کی اکٹھی.پھر الٓمّٓ کی اکٹھی.حٰمٓ کی اکٹھی.اگر سورتیں ان کے حجم کے مطابق رکھی گئی ہیں تو کیا یہ عجیب بات نہیں معلوم ہوتی کہ حروف مقطعات ایک خاص حجم پر دلالت کرتے ہیں.اگر صرف یہی تسلیم کیا جائے تب بھی اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حروف مقطعات کے کچھ معنی ہیں.خواہ یہی معنی ہوں کہ وہ سورت کی لمبائی اور چھوٹائی پر دلالت کرتے ہیں.
Page 22
مگر حق یہ ہے کہ ایک قسم کے حروف مقطعات کی سورتوں کا ایک جگہ پر جمع ہوجانا بتاتا ہے کہ ان کے معنوں میں اشتراک ہے اور یہ حروف سورتوں کے لئے بطور کنجیوں کے ہیں.حروف مقطعات کے معانی کا استنباط قرآن کریم سے میرے نزدیک حروف مقطعات کے معنوں کے لئے ہمیں قرآن کریم ہی کی طرف دیکھنا چاہیے.پہلی سورتوں میں الٓمّٓ آیا تھا.چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے یہی حروف تھے اور ان کے بعد ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ١ۛۖۚ فِيْهِ١ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۠(البقرۃ:۳) کا جملہ تھا.اس کے بعد آل عمران میں الٓمّٓ آیا.جس کے بعداللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ١ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ (آل عمران:۳،۴) آیا.یاد رکھنا چاہیے کہ حق اور لاریب کے دراصل ایک ہی معنی ہیں پس بقرہ میں بھی الٓمّٓ کے بعد ایسی کتاب کا ذکر تھا جس میں ریب نہ ہو اور اس جگہ بھی.پھر اعراف میں الٓمّٓصٓ آیا اور اس کے بعدكِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (الاعراف :۳).کی آیت رکھی گئی.گویا یہاں بھی لاریب فیہ والی کتاب کا ذکر ہوا ہے.کیونکہ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ ، لَا رَيْبَ١ۛۖۚ فِيْهِ کتاب پر ہی دلالت کرتا ہے.ان ابتدائی سورتوں کے بعد وقفہ دے کر عنکبوت الٓمّٓ سے شروع ہوتی ہے.فرماتا ہےالٓمّٓ.اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْۤا اَنْ يَّقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ.وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ (العنکبوت:۲تا۴).ان آیات میں بھی ایک یقینی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے.چنانچہ امتحان شک اور ریب کے دور کرنے پر ہی دلالت کرتا ہے.پس اس سورت میں بھی وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ وغیرہ میں تھا.مگر بقرہ میں انسان بحیثیت مجموعی مخاطب تھے اور یہاں مومنوں سے کہا گیا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابھی شک تمہارے دلوں میں باقی ہو.اور ہم تم سے معاملہ کاملین والا کرناشروع کردیں؟ سورۂ روم میں بھی یہی مضمون ہے.گو بہت باریک ہو گیا ہے.فرماتا ہےالٓمّٓ.غُلِبَتِ الرُّوْمُ.فِيْۤ اَدْنَى الْاَرْضِ وَ هُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ(الروم:۲ تا ۴).خدا تعالیٰ کا کلام روم کے متعلق نازل ہوا ہے.اور وہ ضرور پورا ہوکر رہے گا.گویا بجائے سب کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے ایک خاص حصہ کی طرف اشارہ ہے.اور اس کے یقینی ہونے پر زور دیا ہے جیسا کہ من اور س کے حروف سے ظاہر ہے.الٓمّٓ کے معنی سورہ روم کے بعد سورہ لقمان الٓمّٓ سے شروع ہوتی ہے.اس میں فرماتا ہے.الٓمّٓ.تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ.هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ.الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.اُولٰٓىِٕكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ(لقمان:۲ تا ۶).اس سورۃ میں بھی حکیم کا لفظ استعمال کرکے ایک یقینی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.اور گویا بقرہ کے ابتدائی مضمون کو دہرا دیا گیا ہے.اس کے بعد سورۂ سجدہ ہے.
Page 23
اس میں آتا ہے الٓمّٓ.تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ(السجدۃ:۲ ،۳).یہاں بھی ایک بےریب کتاب کا ذکر ہے.پس ان سب آیات سے ظاہر ہے کہ جہاں الٓمّٓ آتا ہے اس کے بعد ایک خاص مضمون آتا ہے اور ایک یقینی علم کے نزول کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے.اب اس امر کی موجودگی میں کس طرح سمجھ لیا جائے کہ یہ الفاظ یونہی رکھ دیئے گئے ہیں؟ پس حق یہی ہے کہ الٓمّٓ کے حروف ازالہ شک اور یقین پر دلالت کرنے کے لئے آتے ہیں.اور وہ چیز جس سے شک دور ہوتا اور یقین پیدا ہوتا ہے کامل علم ہی ہوتا ہے.پس الٓمّٓ کے معنی یہی ہیں کہ انااللہ اعلم.میں اللہ ہوں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں.پس اگر شک کو دور کرنا اور یقین حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے کلام کی طرف توجہ کرو.اور میری کتاب کو پڑھو.الٓرٰکے معنی اب میں الٓرٰ کو لیتا ہوں.ان حروف سے جو سورتیں شروع ہوتی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو وہ بھی ایک ہی مضمون سے شروع ہوتی ہیں.سورۂ یونس میں آتا ہے الٓرٰ١۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ.اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ١ؔؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ(یونس:۲،۳).پھر سورۂ ہود میں آتا ہےالٓرٰ١۫ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ.اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ١ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ.وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ١ؕ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ(ھود:۲ تا ۴).پھر سورہ یوسف میں آتا ہےالٓرٰ١۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ.اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ١ۖۗ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ(یوسف:۲تا۴).پھر سورہ رعد میں آتا ہے الٓمّٓرٰ١۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ١ؕ وَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ.اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ١ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى١ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ(الرعد:۲،۳).یہاں میم کا بھی اور راء کا بھی مضمون آ گیا.پھر سورۂ ابراہیم میں آتا ہے الٓرٰ١۫ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ١ۙ۬ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ١ؕ وَ وَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ(ابراہیم:۲،۳).پھر سورۂ حجر میں آتا ہے الٓرٰ١۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَ قُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ.رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ.ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَ يَتَمَتَّعُوْا وَ يُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ.وَ مَاۤ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ.مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَ مَا يَسْتَاْخِرُوْنَ۠(الحجر:۲،۳،۵،۶).ان سب مقامات
Page 24
پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں دو مضامین پر زور دیا گیا ہے ایک پرانی تاریخ پر.جس میں سے خاص طور پر شریروں کو سزا ملنے کے مضمون کو منتخب کرلیا گیا ہے اور دوسرے پیدائش عالم کے مضمون پر.سورۂ یونس میں استفہام انکاری کے استعمال سے بتایا گیا ہے کہ نذیر و بشیر انبیاء ہمیشہ ہی آتے رہے ہیں.سورہ ہود میں اول تو یہ قاعدہ بتایا ہے کہ کوئی قوم ایک ہی حالت پر قائم نہیں رہتی بلکہ ایک دائرہ کے اندر چکر لگاتی ہے.اور پیدائش عالم کا ذکر کرکے بتایا کہ دنیا کی ترقی قانون ارتقاء کے ماتحت ہے.اس کے بعد سورۂ یوسف میں صاف الفاظ میں تاریخ عالم کی طرف اشارہ کیا ہے.سورۂ رعد میں چونکہ میم زائد تھا اس میں الٓمّٓ اور الٓرٰ دونوں مضمونوں کو جمع کر دیا ہے اور پہلے تو میم کی مناسبت سے ایک یقینی کلام کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے بعد پیدائش عالم کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے.سورئہ ابراہیم میں پھر قانونِ قدرت کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے.اور بتایا ہے کہ اسے دیکھو اس میں تمہیں ایک بیدار آقا کا ہاتھ نظر آئے گا.سورۂ حجر میں پھر پچھلی تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے.اب یہ امر ظاہر ہے کہ واقعات اور قانون کا تعلق دیکھنے سے ہے.حقیقت تک وہی پہنچ سکتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوں.یا جس کی آنکھوں کے سامنے کوئی قانون ظاہر ہو رہا ہو پس ان سورتوں کا رویہ کے ساتھ تعلق ہے.اور الٓرٰ میں یہی دعویٰ کیا گیا ہے.کہ میں اللہ دیکھتا ہوں.نہ تو پرانی تاریخ میری نظر سے پوشیدہ ہے اور نہ قانونِ قدرت کا اجراءیا پیدائش عالم میری نگہ سے مخفی ہے.پس روئیت سے تعلق رکھنے والے امور میں بھی میری ہی ہدایت کافی ہوسکتی ہے.مقطعات والی سورتوں میں مابہ الاشتراک ایک اور بات بھی حروف مقطعات کے متعلق یاد رکھنی چاہیے کہ گو حروفِ مقطعات کے مضامین حروف کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں لیکن ایک امر میں سب حروف مشترک ہیں اور وہ یہ کہ جو سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان کے مضمون کی ابتداء وحی الٰہی کے ذکر سے ہوتی ہے.اکثر میں تو صاف الفاظ میں کتاب یا قرآن کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے اور چند ایک میں کسی پرانی کتاب کی طرف اشارہ ہے.جیسے سورۂ مریم میں.یا کسی خاص کلام کی طرف اشارہ ہے.جیسا سورۂ روم میں.
Page 25
تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ۰۰۲ یہ کامل( اور) پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں.حلّ لُغات.تِلْکَ تِلْکَ اسم اشارہ ہے.اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے.أل ألحرفِ تعریف ہے اور اس کے مختلف معنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس لفظ پر یہ آئے اس کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی جنس میں سے کامل وجود ہے.آیۃ آیَاتٌ آیَۃٌ کی جمع ہے.جس کے معنی علامت، نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں.قرآن کریم کے ہر اک ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہو آیَۃٌ کہتے ہیں (تاج ).آیت کی وجہ تسمیہ میرے نزدیک قرآنِ کریم میں وارد فقروں کا نام آیۃ اسی حکمت سے رکھا گیا ہے کہ تا لوگ یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے مضامین میں مکمل ترتیب ہے اور ہر فقرہ دوسرے فقرہ کے معانی کے لئے بطور دلیل ہے.بغیر اس کے مدنظر رکھے مطلب پوری طرح نہیں سمجھ میں آسکتا.دوسرے اس لئے بھی کہ ہر ہر ٹکڑا خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے.عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن نے معجزات کا دعویٰ نہیں کیا.حالانکہ قرآن کریم تو اپنے ہر فقرہ کا نام آیت رکھ کر اسے معجزات پر مشتمل بلکہ خود معجزہ قرار دیتا ہے.کِتَابٌ اَلْکِتَابُ مَصْدَرٌ یہ لفظ دراصل کَتَبَ کی مصدر ہے.کَتَبَ الْکَتِیْبَۃَ جَمَعَھَا.لشکر کو جمع کر لیا.کَتَبَ السِّقَاءَ.خَرَزَہٗ بِسَیْرِیْنِ.چمڑے کی تنیوں کے ساتھ اسے سی دیا(تاج ).انہی معنوں کی رو سے کتاب کتاب کہلاتی ہے.کیونکہ اس میں مضامین کو جمع کر دیا جاتا ہے اور مختلف اوراق کو ایک جگہ اکٹھا کرکے سی دیا جاتا ہے.کتاب کے معنی اس خالی کاغذوں کے مجموعہ کے بھی ہوتے ہیں جس پر کچھ لکھا جائے اور کتاب تحریر کو بھی کہتے ہیں اور کتاب کے معنی فرض اور حکم اور اندازہ کے بھی ہوتے ہیں اور کتاب خط کو بھی کہتے ہیں.(اقرب) حَکِیْمٌ حَکِیْمٌ عالم، صَاحِبُ الْحِکْمَۃِ، یعنی حکمت والا.اَلْمُتْقِنُ لِلْاُمُوْرِ.تمام کاموں کو اچھی طرح کرنے والا.جس کے کاموں کو کوئی بگاڑ نہ سکے(اقرب).اَلْمُحْکِمُ.یعنی مضبوط(مفرد).حِکْمَۃٌ کے معنی ہیں.عدل، علم، حلم، نبوت ، مَایَمْنَعُ مِنَ الْـجَھَالَۃِ.یعنی ہر وہ بات جو جہالت سے روکے.کُلُّ کَلَامٍ مُوَافِقٍ لِلْحَقِّ.ہر وہ کلام جو سچائی کے مطابق ہو.بعض کے نزدیک اس کے معنی وَضْعُ الشَّیْءِ فِی مَوْضِعِہٖ کے ہیں.یعنی ہر امر کو اس کے مناسب حال طور پر استعمال کرنا.اور صَوَابُ الْاَمْرِوَ سَدَادُہٗ بات کی حقیقت اور اس کا مغز.(اقرب)
Page 26
حَکَم جو حکیم کا مادہ ہے.اس کے معنی ہیں مَنَعَ مَنْعًا لِاِصْلَاحٍ.اصلاح کی خاطر کسی کو کسی کام سے روکنا.اور اسی وجہ سے جانور کی لگام کو حَکَمَۃً کہتے ہیں.ایک شاعر کہتا ہے ؎ أَبَنِیْ حَنِیْفَۃَ أَحْکِمُوْا سُفُہَاءَ کُمْ اے بنی حنیفہ اپنے بیوقوفوں کو سمجھاؤ اور بری باتوں سے روکو.(مفردات) تفسیر.اس آیت میں خَیْرُالْکَلَامِ مَاقَلَّ وَ دَلَّ کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے.لفظ تھوڑے ہیں لیکن اس قدر وسیع معانی پر مشتمل ہیں کہ قرآن کریم کے کمالات کا خاکہ کھینچ دیتے ہیں.الفاظ کے جو معنی اوپر لکھے گئے ہیں ان پر غور کرو اور دیکھو کہ کس قدر وسیع مطالب کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے.اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جو اپنے اندر علوم رکھتی ہے.عدل کی تعلیم دیتی ہے جہالت سے روکتی ہے.تمام سچائیاں اس میں پائی جاتی ہیں.محل اور موقع کے لحاظ سے تعلیم دیتی ہے.لوگوں کی اصلاح کی غرض سے تعلیم دیتی ہے.اس میں بڑی پکی باتیں ہیں.عربی زبان کی وسعت دیکھو.ایک لفظ میں کتنے دعویٰ کر دیئے ہیں.اور بتایا ہے کہ یہ ہیں ہمارے کام.پس اب تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقع میں اس میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں.اگر پائی جاتی ہیں تو پھر اس کا انکار خلاف عقل و دانش ہوگا.مگر کون کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ امور نہیں پائے جاتے؟ اشارہ بعید کا لفظ اختیار کرنے کی وجہ تِلْکَ کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے.اور اٰیٰتُ الْکِتٰبِ تو بعید نہیں.جن کی طرف بظاہر اشارہ ہے.پس سوال یہ ہے کہ تِلْکَ کا لفظ جو اشارہ بعید کے لئے ہے.یہاں پر کیوں لایا گیا ہے.بعض نے اس کے متعلق کہا ہے کہ تورات وغیرہ پہلی کتابوں میں اس کتاب کی نسبت پہلے سے خبر دی ہوئی تھی.پس تِلْکَ کے ساتھ ان مبشر آیات کی طرف اشارہ ہے جن میں اس کلام پاک کی خبر دی گئی تھی.اور بتایا ہے کہ وہ مبشرات اس کتاب کی آیتیں ہیں.یعنی ان کا وجود اس کتاب کی آیتوں کے ذریعہ سے پورا ہوتا ہے.اور بعض کا یہ خیال ہے کہ خدا نے پہلے مکمل کتاب لکھ چھوڑی تھی.اس میں سے وہ وقتاً فوقتاً آیتیں اتارتا رہتا ہے.پس ان کے نزدیک تِلْکَ کا اشارہ اس پہلی مکمل شدہ کتاب کی آیتوں کی طرف ہے.بعض کہتے ہیں کہ جس طرح مُشار اِلَیْہ کے بُعد مکانی کے بتانے کے لئے تِلْکَ آتا ہے ایسا ہی اس کے درجہ کے بُعد کے اظہار کے لئے بھی آتا ہے.اور یہاں پر درجہ کے بُعد اور تعظیم کے لئے اس لفظ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے.یہ سب مفہوم اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں.مگر میرے نزدیک ایک اور مفہوم بھی ہے جو درجہ والی بات سے ملتا ہے مگر اس سے کسی قدر الگ بھی ہے.اور وہ یہ کہ آگے آتا ہے اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا کیا لوگ اسے عجیب بات یعنی
Page 27
ان ہونی بات سمجھتے ہیں.ان ہونی یا عجیب بات اسی کو کہتے ہیں جسے انسان بعیدازقیاس سمجھتا ہے.پس اگلی آیت سے معلوم ہوا کہ کفار قرآن کریم کے مضمون کو بعیدازقیاس باتیں قرار دیا کرتے تھے.اس لئے مخاطبین کے عقیدہ کے مطابق تعریضاً فرمایا کہ وہ ان ہونی بات (یعنی جسے تم ان ہونی خیال کرتے ہو) ایک نہایت ہی پختہ کتاب کی آیتیں ہیں.یعنی بجائے اس کے کہ انہونی ہوں ان سے زیادہ کوئی اور بات یقینی ہو ہی نہیں سکتی.پس تِلْکَ کا لفظ ان کے استبعاد کو مدنظر رکھتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے.ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا.وَّ نَرٰىهُ قَرِيْبًا.(المعارج:۷،۸) جس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ لوگ اسے مستبعد خیال کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ امر یقینی ہے.غرض جس چیز کے متعلق تعجب اور استبعاد ہو.وہ بھی دور کی سمجھی جاتی ہے.پس ان لوگوں کے خیالات کے مطابق فرمایا کہ وہ چیز جو تمہیں دور کی نظر آتی ہے اور جسے تم بعیدازعقل سمجھتے ہو اسے دور کی نہ سمجھو.وہ تو اس کتاب حکیم کی آیتیں ہیں.اور بہرحال پوری ہوکر رہیں گی.اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ کیا لوگوں کے نزدیک ہمارا ان میں سے ایک شخص پر (یہ) وحی کرنا کہ لوگوں کو ہوشیار کر اور جو لوگ اَنْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ ایمان لائے ہیں انہیں بشارت دے کہ ان کے لئے ان کے رب کے حضور میں ایک ظاہرو باطن طور پر کامل درجہ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ١ؔؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ۰۰۳ ہے( ایسا) عجیب (امر) تھا (کہ) ان کافروں نے کہہ دیا کہ یہ (شخص) یقیناً یقیناً کھلا کھلا دھوکہ باز ہے.حلّ لُغات.عَـجَبٌ.اَلْعَجَبُ اِنْکَارُمَا یَرِدُ عَلَیْکَ یعنے جب کوئی ایسا امر پیش آئے کہ اس کے ماننے میں طبیعت کو انقباض اور انکار ہو تو اس حالت انکار کو عجب کہتے ہیں.اِسْتِطْرَافَہ.پیش آمدہ امر کو پسند کرنے کو بھی عجب کہتے ہیں.رَوْعَۃٌ تَعْتَرِی الْاِنْسَانَ عِنْدَ اِسْتِعْظَامِ الشَّیْءِ.یعنی اس حالت رُعب کو بھی عجب کہتے ہیں جو انسان پر کسی چیز کو بہت ہی بڑا سمجھنے کے وقت طاری ہوتی ہے.وَمِنَ اللہِ.اَلرَّضٰی اور جب اللہ کی طرف اس لفظ کو منسوب کیا جاوے تو اس کے معنی پسندیدگی کے ہوتے ہیں.(اقرب)
Page 28
رَجُلٌ اَلرَّجُلُ خِلَافُ الْمَرْأَۃِ یعنی مرد.اَلْکَامِلُ فِی الرُّجُوْلِیَّۃِ وہ شخص جس میں مردوں والے کمالات بدرجہ اتم پائے جائیں.(اقرب) وَحْیٌ اَوْحَیْنَا وَحْیٌ سے ہے وَحْیٌ کے معنی مفردات راغب میں لکھے ہیں.اَصْلُ الْوَحْیِ.اَلْاِشَارَۃُ السَّرِیْعَۃُ وحی کے اصل معنی تیزی سے اشارہ کرنے کے ہیں.لفظ وحی کلام الٰہی کی ان تمام قسموں کے لئے بولتے ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مرضی سے مطلع فرماتا ہے.میرے نزدیک وحی کا لفظ اس کلام کے لئے اسی بناء پر چنا گیا ہے کہ علوم روحانیہ الفاظ میں پوری طرح بیان نہیں ہوسکتے.صرف ان کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے.پس خود اس نام سے ہی کلام کی رفعت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے.اَنْذِرْ اَنْذَرَ کا صیغۂ امر ہے.اس کی مصدر اِنْذَارٌ ہے اور الفاظ نَذْرٌ، نُذْرٌ، نُذُرٌ اور نَذِیْرٌ بھی اس معنی میں آتے ہیں.کہتے ہیں اَنْذَرَہٗ بِالْاَمْرِ.اَعْلَمَہٗ وَحَذَّرَہٗ مِنْ عَوَاقِبِہٖ قَبْلَ حُلُوْلِہٖ یعنی کسی امر کی حقیقت سے اسے آگاہ کیا.اور اس امر کے نتائج کے ظاہر ہونے سے پہلے اسے ہوشیار کر دیا اور کہتے ہیں اَنْذَرَہٗ خَوَّفَہٗ فِیْ اِبْلَاغِہٖ یُقَالُ اَنْذَرْتُ الْقَوْمَ سَیْرَ الْعَدُوِّ اِلَیْھِمْ فَنَذَرُوْا یعنی اَنْذَرَہٗ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خبر پہنچاتے ہوئے خوب ہوشیار کیا چنانچہ جب کہتے ہیں اَنْذَرْتُ الْقَوْمَ سَیْرَ الْعَدُوِّ تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں نے قوم کو دشمن کی پیش قدمی سے خوب ہوشیار کیا.اور اس کا فعل لازم یا مطاوع نَذَرَ ہے جس کے معنی ہیں وہ ہوشیار ہو گیا.(اقرب) قَدَمٌ اَلْقَدْمُ اَلرِّجْلُ.پاؤں.اَلسَّابِقَۃُ فِی الْاَمْرِ خَیْرًا کَانَ اَوْشَرًّا.کسی بات میں کمال کا حاصل ہونا.خواہ بری بات ہو یا اچھی.کہتے ہیں لِفُلَانٍ فِی کَذَا قَدَمٌ صِدْقٍ اَوْقَدَمُ سُوْءٍ.فلاں شخص کو فلاں اچھی بات میں کمال حاصل ہے.یا فلاں بری بات میں کمال حاصل ہے.اَلْقَدَمُ.اَلرَّجُلُ لَہٗ مَرْتَبَۃٌ فِی الْخَیْرِ.قدم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جسے کسی اچھی بات میں کوئی خاص درجہ حاصل ہو.اَلْقَدَمُ.الشَّجَاعُ.قدم بہادر (مرد یا عورت) کو بھی کہتے ہیں.اور کہتے ہیں وَضَعَ الْقَدَمَ فِیْ عَمَلِہٖ اس نے اس کام کو شروع کر دیا.(اقرب) صِدْقٌ اَلصِّدْقُ یُعَبَّرُعَنْ کُلِّ فِعْلٍ فَاضِلٍ ظَاہِرًا وَبَاطِنًا بِالصِّدْقِ فَیُضَافُ اِلَیْہِ ذٰلِکَ الْفِعْلُ الَّذِیْ یُوْصَفُ بِہٖ نَحْوَ قَوْلِہٖ تَعَالیٰ فِیْ مَقْعدِ صِدْقٍ وَاَنَّ لَھُمْ قَدَمَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِّی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِیْنَ (مفردات) صدق سے مراد ہر وہ فعل ہوتا ہے جو ظاہر و باطن میں خوبی رکھتا ہو.اور جس فعل کی صدق کو صفت بنانا ہو اس کو صدق کی طرف مضاف کر دیتے ہیں.جیسے کہ قرآن کریم میں ہے.فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ (القمر:۵۶ )
Page 29
فلاں شخص ظاہر و باطن طور پر اچھی جگہ میں ہے.یا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ (یونس :۳) انہیں ظاہر و باطن طور پر اچھا درجہ حاصل ہے.یاوَ اجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ.(الشعراء:۸۵ ) مجھے ظاہر و باطن طور پر اچھی تعریف حاصل ہو.یعنی میرا ذکر خیر کے ساتھ صرف لوگوں کی زبان پر ہی نہ ہو بلکہ واقع میں بھی میرے نیک کام دنیا میں قائم رہیں.اور میری تعریف جھوٹی نہ ہو یعنی لوگ غلو کرکے مجھ سے شرک نہ کرنے لگ جائیں.یا فرمایا ہے کہ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ (بنی اسرائیل : ۸۱) مجھے اس طرح کا داخلہ عطا ہو جو ظاہر و باطن میں اچھا ہو اور میں اس طرح اپنے شہر سے نکلوں کہ جو ظاہر و باطن میں اچھا ہو.یعنی اس میں بزدلی اور کمزوری ایمان کا کوئی شائبہ نہ ہو.اورا س کے نتائج نہایت اعلیٰ ہوں.سٰحِرٌ سٰـحِرٌاسم فاعل ہے.اور سَحَرَ سے نکلا ہے.اس کے مصدر سِحْرٌ کے معنی ہیں.کُلُّ مَا لَطُفَ مأخَذُہٗ وَدَقَّ.ہر وہ چیز جس کا ماخذ یا جڑ نہایت باریک اور پوشیدہ ہو.اَلْفَسَادُ فساد.اِخْرَاجُ الْبَاطِلِ فِی صُوْرَۃِ الْحَقِّ.جھوٹ کو سچ کی شکل میں پیش کرنا وَاِطْلَاقُہٗ عَلٰی مَا یَفْعَلُہٗ مِنَ الْحِیَلِ حَقِیْقَۃً لُغْوِیَّۃً وَمِنْہُ اِنَّ مِنَ الْبَیَانِ لَسِحْرًا اور اس لفظ کا استعمال حیلوں اور فریبوں پر لغت کے اصلی معنوں کے مطابق ہے.اور اسی کے مطابق کہتے ہیں کہ بعض کلام بھی سحر ہوتا ہے.(اقرب) سبب نزول مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ کفار نے طنزاً کہا کہ لَمْ یَجِدِاللہَ رَسُوْلًا اِلَّا یَتِیْمُ اَبِیْ طَالِبٍ (الکشاف للزمخشری تفسیر سورۃ یونس :۲) کہ خدا تعالیٰ کو ابوطالب کے یتیم کے سوا اور کوئی رسول نہ ملا؟ کہتے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور بتایا کہ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں.کفار کا ایک طنز نزول کے اسباب مقرر کرنا تو خیر ایک ذوقی امر ہے.قرآن کریم کی آیات تو بہرحال اترنی ہی تھیں.مگر اس تاریخی واقعہ سے یہ بات ضرور معلوم ہوجاتی ہے کہ کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نظر سے دیکھتے تھے.اور آپ کی تحقیر کرنے کے لئے کیسے کیسے مضمون ایجاد کرتے تھے.ابوطالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے.اور دادا کی وفات کے بعد آپ ان کی کفالت میں آگئے تھے.ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب کرنا اور آپ کے والد کی طرف منسوب نہ کرنا اس کے صرف یہ معنی تھے کہ آپؐ پر طعن کریں.کہ ایسا غریب آدمی جس کو ایک اور شخص نے پالا تھا.بھلا خدا کا رسول ہوسکتا ہے.نادانوں نے یہ تو نہ سوچا کہ حضرت ابوطالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے کوئی غیر نہ تھے.باپ کی عدم موجودگی میں چچا کے گھر پلنے کا بچہ کو اخلاقاً حق ہوتا ہے.کیونکہ اہلی زندگی کی بنیاد ہی اس قدیم عہد پر ہے کہ ایک دوسرے کا مصیبت کے وقت میں نائب بنے گا.
Page 30
چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو پالا.اگر ابوطالب کا کوئی بیٹا رہ جاتا اور عبداللہ زندہ ہوتے تو وہ ان کے گھر پلتا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بھی غریب تھے اور صرف غربت کا اظہار ان کی طرف آپ کو منسوب کرکے بھی ہوسکتا تھا.مگر انہوں نے ابوطالب کا یتیم کہہ کر اس امر کا اظہار کرنا چاہا کہ یہ شخص دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہمیں بادشاہت کے وعدے دلاتا ہے.تفسیر.کفّار کے تعجب کا ایک باعث کفار کو اس پر تعجب تھا کہ انہی میں سے ایک آدمی پر کس طرح وحی آگئی.گری ہوئی قوموں میں یہ احساس ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے کہ ہم میں سے بڑے آدمی نہیں پیدا ہوسکتے.گویا کفار اپنی حالت سے ایسے مایوس ہوگئے تھے کہ وہ یقین ہی نہیں کرسکتے تھے کہ ان کا علاج ان کے اندر موجود ہے.ان کا خیال تھا کہ ان کو بڑھانے اور ترقی دینے اور ان کا علاج کرنے کے لئے باہر سے کسی کو آنا چاہیے.یہی حال آج کل بہت سے مسلمانوں کا ہے.وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ؑ ہی آسمان سے آکر ہمیں ذلت اور ادبار سے نکالیں گے.ہم میں سے ایسا شخص نہیں پیدا ہوسکتا جو ہمارا علاج کرے.اس امر میں انہیں پہلی قوموں سے کس قدر موافقت حاصل ہے وہی مایوسی ہے اور وہی طریقِ علاج! وہ لوگ جو قومی ترقی کے لئے یا تو امنگ ہی نہ رکھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ خارجی علاج کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا جب ان میں سے ان کے بھائی نے دعویٰ کیا کہ میں ہی تمہارا علاج کروں گا اور ترقی کی طرف لے جاؤں گا تو ان کی حیرت کی حد نہ رہی.وہ حیران ہو گئے.کہ جو بات ناممکن تھی اسے ممکن کرنے کا اس نے کیونکر دعویٰ کر لیا؟ دوسرا باعث دوسری بات جو ان کے لئے حیرت انگیز بن گئی یہ تھی کہ اس مدعی کا دعویٰ ہے کہ مجھے لوگوں کو ہوشیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے.یعنی بعض پرانی باتوں کو چھوڑ دو اور بعض نئی باتوں کو اختیار کرو.ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ یہ بات قابل تعجب ہوا کرتی ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کو توڑ دو.اور نیا نظام اختیار کرو؟ کفار کی یہ دونوں باتیں متضاد ہیں.ایک طرف تو ان میں اتنی مایوسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاج کے لئے ہم میں سے کوئی نہیں آسکتا اور دوسری طرف وہ اس بات پر لڑتے ہیں کہ ہمارا نظام کیوں بدلتے ہو؟ یہ گری ہوئی قوموں کی حالت ہوتی ہے.وہ چاہتی ہیں کہ نہ کچھ چھوڑنا پڑے اور نہ کچھ کرنا پڑے.ایک شخص باہر سے آکر ان کے موجودہ نظام کو قائم رکھتے ہوئے انہیں ترقی کی طرف لے جائے.انہیں نہ تعلیم حاصل کرنی پڑے نہ محنت و مشقت کرنی پڑے نہ بری باتوں کو چھوڑنا پڑے.بلکہ ایک شخص باہر سے آئے اور دوسروں کو مار دے اور سب کچھ انہیں حاصل ہو جائے.وہ یہ نہیں خیال کرتے کہ اگر ان کا پہلا نظام درست ہوتا تو ذلت اور ادبار میں وہ پڑتے ہی کیوں؟
Page 31
پس ان کا موجودہ نظام توڑ کر ہی کام چل سکے گا.ایک اور موجب تعجب تیسری بات قابل تعجب ان کے لئے یہ تھی کہ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ میرے کہنے پر چل کر جو لوگ اس نظام کو بدلا لیں گے وہ ترقی کر جائیں گے.حالانکہ ان کے نزدیک اول تو وہ لوگ بہترین دماغ کے نہ تھے.بلکہ ادنیٰ درجہ کے تھے.دوم وہ لوگ قوم کی مخالفت پر کھڑے تھے.سوم ناممکن بات کو ممکن بنادینے کا دعویٰ کرتے تھے.چونکہ کوئی قوم اسی وقت ترقی کرسکتی ہے کہ اس کے کام کرنے والے لوگ بہترین دماغ کے ہوں.اس کا آپس میں اتحاد ہو.اور وہ ایسے مقاصد کے لئے کھڑی ہو جن کا حاصل کرنا ممکن ہو.اور مسلمانوں کو وہ ان سب باتوں سے محروم سمجھتے تھے.اس لئے تعجب کرتے تھے کہ یہ کس طرح کامیاب ہو جائیں گے.یہ کیونکر پہلے نظام کو توڑ دیں گے.اور اس کی جگہ ایک اور نظام ایسا قائم کریں گے جو ظاہر اور باطن طور پر اچھا ہوگا.جس سے یہ بادشاہ بن جائیں گے اور روحانی طور پر ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوجائے گا.عِنْدَرَبِّھِمْ اس لئے فرمایا کہ روحانی اور جسمانی دونوں ترقیاں ضروری ہوتی ہیں.پس اس ہستی کی طرف نسبت دے کر جس کے قبضہ میں یہ دونوں ترقیاں ہیں کامل کامیابی کی طرف اشارہ کر دیا.اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ.کفار نے اوپر کی بات کو سن کر کہا کہ یہ شخص باتیں خوب بناتا ہے.حتیٰ کہ جھوٹ کو سچ کر دکھاتا ہے.اور انسانی فطرت کو اپیل کرکے جو ڈرنے والے ہیں ان کو ڈرا کر جو لالچی ہیں انہیں لالچ دلا کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے.یہی اعتراض آج کل مسیحی مصنف کرتے ہیں.اور کہتے ہیں کہ عرب کے جاہلوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف دلا کر یا لالچ دلا کر اپنے ساتھ ملا لیا.حالانکہ کفار کا اعتراض بتاتا ہے کہ یہ نکتہ ان عرب کے جاہلوں کو بھی معلوم تھا پھر وہ کس طرح دھوکہ میں آگئے.حق یہ ہے کہ تَشَابَھَتْ قُلُوْبُھُمْ دونو کے دل مل گئے ہیں.ورنہ وہ کون سا مذہب ہوگا جو یہ کہے کہ جو مجھے مانے گا دوزخ میں جائے گا اور جو نہ مانے گا جنت حاصل کرے گا.اگر سچائی کے ماننے کے انعامات کا ذکر لالچ ہے تو کوئی سچائی بغیر لالچ کے نہیں ہوسکتی.یہ لوگ حضرت مسیح ؑ کے متعلق کیا کہیں گے جنہوں نے جنت کی کنجیوں کا وعدہ پطرس کو دیا اور اعلان کیا کہ ہر ایک کو جو اس کی تعلیم پر نہیں چلتا وہ خدا کی بادشاہت سے محروم رہے گا اور ماننے والوں کے لئے انعامات کے وعدے کئے.(متی ب۱۶، ب۱۸، ب۱۹)
Page 32
اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ تمہارا رب یقیناً اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ وقتوں میں پیدا کیا اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ١ؕ مَا مِنْ پھر عرش پرقرار فرما ہوا.وہ ہر امر کا انتظام کرتا ہے (اس کے حضور میں) کوئی بھی( کسی کا) شفیع شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ١ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ١ؕ نہیں (ہوسکتا) مگر ہاں اس کی اجازت کے بعد.وہ( مذکورہ بالا صفات والا) ہے(اور وہی ہے) تمہارا رب اس اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ۰۰۴ لئے تم اس کی عبادت کرو.کیا تم پھر( بھی باوجود ان باتوں کے) نصیحت حاصل نہیں کرو گے.حلّ لُغات.رَبٌّ اَلرَّبُّمالک، آقا یا مُطَاع مستحق یا صَاحِبُ الشی ءِ یعنی کسی چیز والا.رَبَّ الشَّیْءَ.جَمَعَہٗ اس چیز کو جمع کیا مَلَکَہٗ اس کا مالک ہوا.اَلْقَوْمَ سَاسَھُمْ وَکَانَ فَوْقَھُمْ قوم پر حکومت اور سیاست کی.النِّعْمَۃَ : زَادَھا نعمت کو بڑھایا.اَلْاَمْرَ: اَصْلَحَہٗ وَاَتَمَّہٗ کام کو درست اور مکمل کیا.الدُّھْنَ: طَیَّبَہٗ واَجَادَہٗ.تیل میں عمدگی اور خوبی پیدا کی.الصَّبِیَّ: رَبَّاہُ حَتّٰی اَدْرَکَ بچہ کی تربیت کی حتیٰ کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ گیا.(اقرب) اَللّٰہُ اللہُ اِسْمٌ بَارِیءُ الْوَجُوْدِ (اقرب) تمام موجودات کو ہستی بخشنے والی ذات کا نام.خَلَقَ خَلَقَ الْاَدِیْمَ: قَدَّرَہٗ قَبْلَ اَنْ یَّقْطَعَہٗ.کھال کو کاٹنے سے پہلے اس کی اس شکل کا اندازہ کیا جس کے مطابق اسے کاٹنے کاا رادہ ہے.الْشَّیْءَ: اَوْجَدَہٗ وَاَبْدَعَہٗ عَلٰی غَیْرِ مَثَالٍ سَبَقَ پیدا کیا.عدم سے وجود بخشا.ایجاد کیا.اختراع کیا.الْاِفْکَ: اِفْتَرَاہُ اپنے پاس سے بات گھڑ لی.اَلْکَلَامَ وَغَیْرَہٗ: صَنَعَہٗ تیار کیا.لِشَیْءَ: مَلَّسَہٗ وَلَیَّنَہٗ ہموار اور صاف کیا.الْعُوْدَ: سَوَّاہُ درست اور ہموار کیا.(اقرب) سَمَاءٌ السَّمٰوٰتُ.سَمَائٌ کی جمع ہے.اَلسَّمَآءُ.آسمان.کُلُّ مَاعَلَاکَ فَاَظَلَّکَ.ہر اوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز.سَقْفُ کُلُّ شَیْءٍ وَبَیْتٍ چھت رَوَاقُ الْبَیْتِ برآمدہ.ظَھْرُالْفَرَسِ گھوڑے کی پیٹھ.اَلسَّحَابُ.بادل.اَلْمَطَرُ بارش.اَلْمَطَرَۃُ الْجَیِّدَۃُ ایک دفعہ کی برسی ہوئی عمدہ بارش.اَلْعُشْبُ سبزہ و گیاہ.(اقرب)
Page 33
ارض الارضکرۂ زمین.کُلُّ مَاسَفَلَ ہر نیچے کی چیز.(اقرب) یوم ایَّامٌ یوم کی جمع ہے.اَلْیَوْمُ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلَی غُرُوْبِ الشَّمْسِ.دن کا وقت اَلْوَقْتُ مُطْلَقًا.مطلق وقت جو بھی اور جتنا بھی ہو.(اقرب) اسْتَوٰی اِسْتَویاِعْتَدَلَ.اعتدال اختیار کیا.الطَعامُ: نَضَجَ پک کر تیار ہو گیا.العودُ من اعوجاجٍ : اِسْتَقَامکجی دور ہوکر سیدھا اور درست ہو گیا.الرجل: اِنْتَھی شَبَابَہٗ وَبَلَغَ اَشُدَّہُ أوْ اَرْبَعِیْنَ سَنَۃً وَاسْتَقَامَ اَمْرَہٗ نشوونما کے کمال کو پہنچ گیا.اپنی جسمانی ترقی کا کمال پالیا.اس کے امور کو درستی حاصل ہو گئی.علٰی ظھر دابۃ: استقرّ قرار پذیر ہو گیا.متمکن ہو گیا.علیہ: استولی وظَھَرَ استیلا اور غلبہ پالیا.لہ والیہ: قَصَدَ متوجہ ہوا.(اقرب) عرش عَرَشَ عَرْشًا: بَنٰی بِنَاءً مِنْ خَشَبٍ لکڑی کی عمارت بنائی.اَلْبَیْتَ: بَنَاہُ تعمیر کیا.اَلْکَرْمَ: رَفَعَ دَوَاِلَیْہُ عَلَی الْخَشَبِ.بیل کو قرینے سے لگائی ہوئی لکڑیوں پر چڑھایا.(اقرب) اَلْعَرْشُ سَرِیْرُ الْمَلِکِ اورنگ شاہی.اَلْعِزُّ.عزت و غلبہ.قِوَامُ الْاَمْرِ معاملات اور امور کی درستی کا ذریعہ اور مدار.رُکْنُ الشَّیْءِ سہارا.مِنَ الْبَیْتِ :سَقْفُہُ چھت.اَلْخَیْمَۃُ خیمہ.اَلْبَیْتُ الَّذِیْ یُسْتَظَلُّ بِہٖ سایہ کا کام دینے والا گھر شِبْہُ بَیْتٍ مِنْ جَرِیْدٍ یُجْعَلُ فَوْقَہُ الثُّمامُ جھونپڑی.(اقرب) تدبیر یُدَبِّرُتدبیر سے فعل مضارع ہے.دبّرالاَمْرَ: نظر فی عاقبتہ وتفکر انجام اندیشی کی اور سوچا.اعتنی بہ اس کی طرف توجہ دی اور اس کا اہتمام کیا.رتّبہ ونظّمہ ترتیب دی.الوالی اقطاعہ: اَحْسَنَ سیاستھا عمدہ نگرانی اور انتظام کیا.الحدیث نقلہ عن غیرہ نقلًا بیان کیا.علٰی ھلاکہ: احتال علیہ وسعٰی فیہ.ہلاک کرنے کی کوشش کی.(اقرب) امر اَلْاَمْرُ:طلب احداث شیء.طلب انشاء شیء او فعلہ کسی چیز یا کسی کام کو وجود میں لانے یا کرنے کا مطالبہ کرنا.الحال حالت.الشان معاملہ، بات، الشیء چیز، بات.(اقرب) اِذنُ اِذنٌمصدر ہے.اَذِنَ بِہٖ: عَلِمَ جان لینا.بہٖ ولَہٗ: اباح اجازت دی.(اقرب) عبادۃ اعْبُدُوْافعل امر ہے.اس کی مصدر عبادۃ، عبودۃ عبودیۃ ہے.عَبَدَلہ تألہ تمام تر کوشش کے ساتھ پرستش میں لگ گیا.عَبَدَاللّٰہَ طاع لہ وخَضَع وذَلَّ وخَدَمَہ والتزم شرائع دینہ ووحّدہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن گیا.اپنے آپ کو اسی ایک کا بنا کر اس کے احکام کا پابند ہو گیا.(اقرب)
Page 34
تذکر تَذکَّرونصیغہ جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معروف ہے.تذکر الشیء: یاد کیا.(اقرب) نصیحت اور تعلیم کو قبول کیا.(تاج) ترتیب: قرآن کریم کی عادت ہے کہ جس آیت کے مضمون کے متعلق کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب اگلی آیت یا اگلی آیات میں دے دیتا ہے.اور بسا اوقات اس اعتراض کو بیان بھی نہیں کرتا.صرف جواب ہی دے دیتا ہے.گویا وہ پڑھنے والے کے ذہن کے افکار میں اور قرآن کریم کے مضامین میں ایک کڑی بنا دیتا ہے.اور اس طرح پڑھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ جو سوال اس کے ذہن میں آتا ہے قرآن کریم اس کا جواب ساتھ کے ساتھ دیتا جاتا ہے.جو لوگ اس کے اس لطیف پیرایہ سے ناواقف ہیں وہ ایسے مقامات پر کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس کی آیات میں ترتیب نہیں.حالانکہ اصل نقص ان کے تدبر کا ہوتا ہے.اس آیت میں بھی ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے جو پہلی آیت سے پیدا ہوتا تھا.اور وہ یہ کہ مسلمان ترقی کس طرح کریں گے.ان کی ترقی کے سامان تو کوئی نظر نہیں آتے.تفسیر.تدریج تکمیل چونکہ پہلی آیت میں مسلمانوں کے لئے ایک پائدار کامیابی کی بشارت دی تھی اور ایسے وقت میں دی تھی جبکہ مسلمانوں کے لئے ان کے گھروں میں بھی امن نہ تھا.اور سب ملک دشمن تھا اس لئے قدرتاً یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایسے حالات میںمسلمان کس طرح ترقی کرسکتے ہیں.پس یہ وعدے صرف دھوکا دینے کے لئے ہیں.چنانچہ یہ سوال کفار کے دلوں میں پیدا ہوا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا.یعنی فریب کی باتیں کرنے والا.پس اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا کہ ضروری نہیں کہ ہر امر کی ابتداء ہی میں اس کی ترقی کے سامان اپنی مکمل صورت میں نظر آجائیں.روحانی عالم بھی جسمانی عالم کی طرح ہوتا ہے.آخر زمین و آسمان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے.اگر اس کی طرف سے آنے والے کلام کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تکمیل کے سامان فوراً پیدا ہوجائیں تو چاہیے تھا کہ زمین و آسمان بھی فوراً پیدا ہوجاتے.مگر ایسا نہیں ہوا.ان کی پیدائش چھ دوروں میں ہوئی ہے.(علم طبقات الار ض سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک دور لاکھوں کروڑوں سال کا تھا) پس جس طرح آسمان و زمین کا باریک اور غیرمرئی ذرات سے ایک لمبے عرصہ میں پیدا ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا.اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے ساتھ ہی اسلام کی تکمیل کے سامانوں کا پیدا نہ ہونا اس امر کی علامت نہیں کہ اس کی تکمیل مشکوک ہے اور اس کی بنیاد خدا تعالیٰ نے نہیں ڈالی.الٰہی کاموں کی بنیاد ہمیشہ ایسے سامانوں سے رکھی جاتی ہے جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں.
Page 35
يُدَبِّرُ الْاَمْرَ کہہ کر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت جو کُنْ فَیَکُوْنُ کے الفاظ آتے ہیں یعنی وہ کہتا ہے ہوجا پس ہوجاتا ہے.اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ اپنے حکموں کو فوراً پورا کرواتا ہے.وقت کی حدبندی نہیں کرتا.بلکہ اس کے احکام بھی تدبیر پر مشتمل ہوتے ہیں.یعنی باریک اورمخفی تدابیر سے کام لے کر وہ نتائج پیدا کرتا ہے.اور تدبیر کے معنی ہی یہ ہیں کہ اسباب میں ایسا تغیر کیا جائے کہ طبعی نتائج منشاء کے مطابق پیدا ہوجائیں.اصلاح عالم کا مقام اذن پر موقوف ہے مَا مِنْ شَفِيْعٍ میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والا وجود صرف اس کے حکم سے ہی کھڑا ہوسکتا ہے.اپنے پاس سے کوئی شخص اس رتبہ کو نہیں پاسکتا.پس یہ کس طرح ممکن تھا کہ ایسے تاریک زمانہ میں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا اذن دے کر نہ کھڑا کرتا اور اپنے بندوں کو یونہی چھوڑ دیتا.اس آیت میں بعض امور قابل تشریح ہیں.ان کی تشریح میںذیل میں کرتا ہوں.یوم سے مراد فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ میں یوم سے مراد یہاں سورج سے تعلق رکھنے والا دن نہیں.مجاہد.احمد بن حنبل.ابن عباس بروایت ضحاک (تفسیر ابن کثیر سورة الاعراف زیر آیۃ فی ستۃ ایام) اور زید بن ارقم (روح المعانی سورة الاعراف زیر آیۃ فِیْ سِتَّۃَ اِیَّامٍ) کا مذہب ہے کہ ایک ایک دن سے مراد ہزار ہزار سال ہے.گویا ان کے نزدیک زمین و آسمان چھ ہزار سال میں پیدا ہوئے ہیں.یہ بات انہوں نے اس آیۃ سے اخذ کی ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.(الحج :۴۸) خدا کے نزدیک ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا ہے.یوم کے معنی جیسا کہ پہلے بیان ہوچکا ہے عربی میں مطلق وقت کے بھی ہوتے ہیں.اور یہی معنی یہاں لگتے ہیں کیونکہ دن رات زمین کے سورج کے سامنے گھومنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں.اور اس آیۃ میں سورج اور چاند اور زمین کی پیدائش کا ذکر ہے.پس اس وقت یہ دن رات ہوتے ہی نہ تھے.اس لئے یہاں مراد وقت ہے نہ کہ صبح و شام والا دن.پس ان کا یہ استدلال صحیح معلوم ہوتا ہے.مگر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ یوم ہزار ہزار سال ہی کا تھا یہ صحیح نہیں.قرآن مجید نے تو یہ بھی کہا ہے کہ تَعْرُجُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ( المعارج:۵ ) کہ خدا کا ایک دن پچاس ہزار سال کا بھی ہوتا ہے.اگر یہ دن یہاں مراد لیں تو زمین و آسمان کی پیدائش کا عرصہ تین لاکھ سال بنتا ہے.لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے سارے دن ہمیں بتائے ہوں.اگر ہزار سال کا یا پچاس ہزار سال کا اس کا دن ہوتا ہے تو ممکن ہے لاکھ یا پچاس لاکھ یا کروڑ یا ارب سال کا بھی اس کا کوئی دن ہوتا ہو.سائنس سے پتہ لگتا ہے کہ اربوں سال زمین و آسمان کے بننے میں لگے.اور حضرت محی الدین صاحب ابن عربی کے ایک کشف سے بھی ایسا ہی پتہ لگتا ہے.پس حق یہی ہے کہ ہم اس عرصہ کی حدبندی ابھی پوری طرح نہیں
Page 36
کرسکتے.صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض تغیرات ہزار ہزار سال میں ہوئے.بعض پچاس پچاس ہزار سال میں.بعض اس سے بھی بہت زیادہ عرصہ میں.پیدائش عالم کی تفصیل حدیث میں حدیث میں پیدائش عالم کی ایک تفصیل آتی ہے.اس کا ذکر کردینا بھی یہاں ضروری ہے.حضرت ابوہریرۃؓ کی روایت ہے کہ اَخَذَرَسُوْلُ اللہِ صَلّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ بِیَدِیْ وَقَالَ خَلَقَ اللہُ التُّرْبَۃَ یَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ الْجِبَالَ فِیْھَا یَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ فِیْھَا یَوْمَ الْاِثْنَیْنِ وَخَلَقَ الْمَکْرُوْہُ یَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّوْرَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِیْھَا الدَّوآبُّ یَوْمَ الْخَمِیْسِ وَخَلَقَ اٰدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَۃِ اٰخِرُ الْخَلْقِ فِی اٰخِرِ السَّاعَۃِ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَۃِ فِی مَابَیْنَ الْعَصْرِ اِلَی الَّلیْلِ.(تفسیر ابن کثیر زیرآیۃ فی ستۃ ایام سورۃ اعراف) نسائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے مگر دوسرے راویوں کی روایت سے.بخاری اور بعض دوسرے محققین کے نزدیک یہ حدیث مرفوع نہیں.بلکہ ابوہریرہؓ نے اسے کعب الاحبار سے سنا ہے.اس حدیث کی رو سے ہفتہ کے دن زمین کو پیدا کیا.اتوار کے دن پہاڑ پیدا کئے.پیر کے دن درخت، منگل کے دن مصیبتیں اور بلائیں.بدھ کو نور اور برکتیں، جمعرات کو حیوان، جمعہ کے دن عصر سے شام تک دن کی آخری گھڑی میں آدم کو.حضرت مسیح موعودؑ نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ آدم جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا ہوئے.اور اس سے اپنے متعلق استدلال کیا ہے.(خطبہ الہامیہ ضمیمہ (ب) و صفحہ ۱۲۳) پیدائش عالم کا ذکر بائبل میں بائبل میں پیدائش عالم کا ذکرا س طرح ہے.خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی.اس کے بعد خدا نے اجالا پیدا کرکے اندھیرے اور اجالے کو جدا کیا اور یہ پہلا دن ہوا.اور پھر خدا نے پانیوں کے درمیان فضا بنائی اور فضا کو آسمان کہا اور یہ دوسرا دن ہوا.پھر پانی سب اکٹھے ہو گئے اور خشکی نکل آئی.تو وہ زمین ہو گئی.اور جمع شدہ پانی سمندر ہو گئے.اور پھر سبزیاں و نباتات بنائیں اور یہ تیسرا دن ہوا.پھر چاند اور سورج اور ستارے پیدا کئے اور یہ چوتھا دن ہوا.پھر رینگنے والے جانور اور پرندے پیدا کئے اور یہ پانچواں دن ہوا.اس کے بعد مویشی، کیڑے مکوڑے اور جنگلی جانور پیدا کئے اور سب سے آخر انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی مانند پیدا فرمایا.اور یہ چھٹا دن ہوا.(پیدائش باب اول) ستة ایام کی تفصیل قرآن کریم میں قرآن کریم میں سورۂ حٰم سجدہ ع۲ میں چھ دنوں کی تشریح اس طرح کی گئی ہے.قُلْ اَىِٕنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا١ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.
Page 37
وَ جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ١ؕ سَوَآءً لِّلسَّآىِٕلِيْنَ.ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ وَ هِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا١ؕ قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآىِٕعِيْنَ.فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا١ؕ وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ١ۖۗ وَ حِفْظًا١ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.ان آیات کا یوں ترجمہ بنتا ہے کیا تم انکار کرتے ہو اس خدا کا جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا.اور اس کے شریک قرار دیتے ہو.وہ ہے رب العٰلمین اور اس نے پہاڑ بنائے ہیں زمین کے اوپر اور برکتیں ڈالیں اس میں اور رزق رکھا یہ سب کچھ اس نے چار دن میں کیا اور یہ جو اب سب قسم کے سائلوں کے لئے برابر تسلی دینے والا ہے.(یعنی ایسے الفاظ میں جواب دیا گیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور ایک علم طبقات الارض کا ماہر بھی اس سے تسلی پاسکتا ہے) اور آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو کہ دخانی حالت میں تھا.اور اسے اور زمین کو کہا کہ ہمارے حضور میں حاضر ہو جاؤ.پسند ہو یا ناپسند.انہوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہوتے ہیں.پس کامل طور پر بنایا ان کو دو دنوں میں سات آسمانوں کی صورت میں اور ہر آسمان میں اس کے مفوضہ کام کی قابلیت رکھی اور سب سے ورلے آسمان کو روشن ستاروں کے ساتھ مزین کیا.یہ اس خدا کا اندازہ ہے جو غالب اور خوب جاننے والا ہے.فِی اَرْبَعَةٍ اَ یَّامٍ سے مراد اس آیت میں ثم واوکے معنی میں آیا ہے اور اس کے معنی ’’اور‘‘ کے ہیں اور اس کے پہلے جو مضمون بیان ہوا ہے وہ درحقیقت بعد کا ہے.ثم کے ذریعہ سے پہلی بات کی صرف تشریح کی ہے.بعض لوگوں نے ان آیات پر اعتراض کیا ہے کہ یہاں آٹھ یوم بنتے ہیں.خلق الارض دو دن میں.خزانوں اور غذاؤں کا پیدا کرنا چار دن میں اور سات آسمانوں کا بنانا دو دن میں.اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جہاں فِی اَرْبَعَۃِ اَ یَّامٍ فرمایا ہے اس جگہ چار نئے دن مراد نہیں.بلکہ زمین کی پیدائش میں جو دودن فرمائے تھے ان کو ملا کر چار دن فرمائے ہیں.اور مطلب یہ ہے کہ خزانے اور غذائیں دودن میں پیدا کیں.اور پہلے دن ملا کر یہ کل چار دن ہوئے.میرے نزدیک یہ معنی گو زبان کے قواعد کے لحاظ سے درست ہیں مگر اس آیت کے مطالب کے لحاظ سے درست نہیں معلوم ہوتے.اس جگہ زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کرنے کا ذکر نہیں ہے.بلکہ پیدائش کے مدارج بیان کئے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ زمین دو وقتوں یعنی دو دوروں میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد چار وقتوں یعنی دوروں میں اس کے اندر کی وہ قابلیتیں پیدا ہوئی ہیں جو انسان کے بقاء اور ترقی کے لئے ضروری تھیں.اور یہ ذکر نہیں کہ اس زمانہ میں اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی چیز نہیں بنی.اور آسمان کے متعلق جو آیا ہے کہ وہ دو وقتوں میں بنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے چھ دنوں کے بعد بنا.بلکہ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے مکمل ہونے پر بھی
Page 38
دو دور گذرے تھے گووہ الگ دور نہ تھے بلکہ زمین کی پیدائش کا جو زمانہ تھا وہی آسمانوں کا بھی تھا.پس کل روز چھ ہی رہے.آٹھ نہ ہوئے.علم طبقات الارض سے بھی یہی ثابت ہے کہ پیدائش عالم ایک ہی وقت میں ہوئی ہے.زمین بھی اور باقی سیارے بھی ایک ہی وقت میں تکمیل کے مدارج طے کررہے تھے.یہ نہیں کہ زمین پہلے بنی اور پھر دوسرے سیارے یا یہ کہ سیارے پہلے بنے اور پھر زمین.پس جو ہر زمین کے بننے کا وقت تھا اسی وقت اس کا آسمان بھی بن رہا تھا.یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ آسمانی اجرام کی اندرونی قابلیتیں کس قدر عرصہ میں بنیں.فِی سِتَّۃِ اَیَّامٍ میں یَوْمکی مقدار اب رہا یہ سوال کہ یہ یوم یعنی وقت کس کس قدر عرصہ کے تھے.سو اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی تعیین خدا تعالیٰ نے نہیں کی اور اس وجہ سے ہم بھی نہیں کرتے.علم طبقات الارض اور علم ہیئت سے جو امور یقینی طور پر معلوم ہوں ان سے ہم اندازہ کرسکتے ہیں یا اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعہ سے کچھ بتا دے تو وہ ایک اندازہ کرسکتا ہے.ورنہ ہم صرف یہ یقین رکھیں گے کہ دو عظیم الشان دور آسمان و زمین کی پیدائش پر گذرے ہیں.اور یہ سوال کہ ان میں سے ہر اک دور کس قدر عرصہ کا تھا.اسے ہم خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے.اصل بات یہ ہے کہ علم ہیئت اور علم طبقات الارض میں بھی قرآنی اصطلاح کے مطابق ایک عظیم الشان تغیر کو عرصہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور انگریزی میں اسے (PERIOD) کے نام سے موسوم کرتے ہیں جو مفہوم (PERIOD) یعنی عرصہ کا علم ہیئت اور علم طبقات الارض میں ہوتا ہےوہی مفہوم یوم کا قرآنی آیات میں ہے.روحانی عالم کی تکمیل کے سات مدارج اس آیت سے اور بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش عالم میں یہ سنت مقرر کی ہے کہ ہر چیز کی تکمیل ساتویں درجہ پر ہوتی ہے.چھ درجے خلق کے ہوتے ہیں اور ساتواں تکمیل کا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کہ یہ روحانی عالم بھی چھ دوروں میں تکمیل کو پہنچے گا.چنانچہ ایسا ہی ہوا.آپ کے دعویٰ کے بعد پہلی حالت دخان کی تھی یعنی سوائے تاریکی اور دھند کے کچھ نظر نہیں آتا تھا.اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی بعثت سے بجائے دنیا کو کچھ فائدہ پہنچنے کے الٹا کچھ نقصان ہی ہوا ہے اور تفرقہ اور جنگ زیادہ ہو گیا ہے.سب دعاوی بھی مثل دخان کے تھے کہ کوئی ٹھوس چیز ابھی نظر نہ آتی تھی.اس کے بعد دوسرا دور آیا کہ وہ دخان کچھ کچھ سمٹنے لگا.کچھ آدمی آپ پر ایمان لے آئے اور لوگوں کو معلوم ہونے لگا کہ یہ سلسلہ بھی ایک علیحدہ ہستی بن رہا ہے.اس کے بعد اندرونی تغیرات شروع ہوئے.اور جس طرح زمین میں زلازل وغیرہ آتے ہیں اسی طرح اسلام کے خلاف جوش پیدا ہوا.اور زلازل کا
Page 39
ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا.اور پھراس کے بعد اسلام کے پہاڑ یعنی ابوبکرو عمر و عثمان و علی وَغَیْرَہُمْؓ لوگ تیار ہوئے.یہ لوگ انہی زلازل کے سبب سے ممتاز ہوئے.اگر زلازل نہ آتے تو ان کے جوہر بھی نہ کھلتے اور یہ بھی اس مقام کو نہ پہنچتے اس کے بعد پانچواں دور یہ آیا کہ جس طرح زمین میں نبات پیدا کرنے کی قابلیت پیدا ہوئی تھی آپ کی تعلیم بھی سرسبز و شاداب نظرآنے لگی اور لوگ محسوس کرنے لگے کہ یہ ایک خوش گوار تعلیم ہے.اور مختلف علاقوں میں پھیلنے لگی.اس کے بعد جس طرح زمین میں حیوانات پیدا ہونے لگے تھے اسلام کے اندر قوت و طاقت پیدا ہو گئی.اور پھر اس نے دشمنوں کے حملوں کا دفاع شروع کردیا.آخر ساتواں یعنی تکمیل کا دور یہ آیا کہ جس طرح زمین پر انسان پیدا ہوا تھا اور اس نے کل عالم پر حکومت شروع کی تھی خدا تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور طاقت بخشی اور اس کی شریعت جاری ہو گئی اور دنیا پرا س نے حکومت کرنی شروع کر دی.گویا انسان کامل کا دور شروع ہوا.ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ سے اس طرف اشارہ کیا کہ جس طرح وہاں پیدائش عالم کے بعد خدا تعالیٰ عرش پر قرار فرما ہوا تھا اسی طرح یہاں ہوگا.یعنی اسلام کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ مقام تنزل کی طرف رجوع کرے گا اور صرف اسلام ہی کے ذریعے سے آیندہ روحانی ترقیات حاصل ہوں گی جس طرح عالم مادی کے پیدا کرنے کے بعد ہر اک کام قوانین نیچر کی وساطت سے ہوتا ہے اور عام حالات میں خدا تعالیٰ براہ راست کوئی تغیر نہیں فرماتا.شفاعت دوم مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ کا حصہ قابل تشریح ہے.شَفِیْعٌ شَفَعَ سے نکلا ہے.اس کے معنی ہیں دو کر دینا.چنانچہ کہتے ہیں شَفَعَ العَدَدَ وَالصَّلٰوۃَ.ایک کو دو کر دیا یا ایک رکعت پڑھ کر ایک اور پڑھی.اور اسے دو رکعت بنا دیا.اور نَاقَۃٌ شَافِعٌ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں بھی بچہ ہو.اور اس کے ساتھ بھی بچہ ہو(اقرب).گویا وہ اپنے پہلے بچہ کو دو بنا دیتی ہے.لیکن صرف ایک کو دو بنا دینا اس لفظ سے نہیں نکلتا.بلکہ یہ شرط بھی ہے کہ ضَمُّ الشَّیْءِ اِلَی مِثْلِہٖ ہو.یعنی اس قسم کی چیز ملائی جائے یہ نہیں کہ کوئی اونٹ کے ساتھ ایک گھوڑا کھڑا کر دے اور کہہ دے کہ شَفَعْتُ النَّاقَۃُ اونٹ کے ساتھ اونٹ ہی ملایا جائے تب ہی شفع کا لفظ استعمال ہوگا.مسئلہ شفاعت کا حل ان معنوں کو مدنظر رکھنے سے شفاعت کا مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے.اور ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت سے گنہ میں ترقی ہوتی ہے اور لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں.کیونکہ شافع یا شفیع کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ وہ ہم جنس کو آپس میں ملائے.پس گنہ گار اور بدکار کو نیکوں سے ملانا تواس کے مفہوم میں شامل ہی نہیں.بلکہ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جسے خدا تعالیٰ نے شفیع بنایا ہو وہ بدکاروں کو نیک بنا بنا کر پہلی نیک جماعتوں کے ساتھ ملائے یہ معنی اس دنیا کے لحاظ سے ہیں.دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ آخری فیصلہ کے دن جو لوگ ایک
Page 40
بڑی حد تک نیک ہوں صرف بعض خامیاں ان میں ہوں جو ان کو کاملین میں شامل ہونے سے روک رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتا ہو کہ ان کی ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کو نظرانداز کرکے اور ان کی اس جدوجہد کو مدنظر رکھ کر جو وہ اپنی تکمیل کے لئے کرتے رہے ہیں انہیں کاملین میں ہی شامل کر دے تو خدا تعالیٰ سے اذن پاکر امت کا نبی خدا تعالیٰ سے سفارش کرے کہ ان کی تھوڑی تھوڑی خامیوں کو نظرانداز کرکے ہمارے ساتھ ہی شامل سمجھا جائے.یہ معنی اگلے جہان کے متعلق ہیں.اور شفاعت کے لئے شرط ہے کہ اذن سے ہو اور اذن بھی اسی شخص کے متعلق ملے گا جو شخص دل سے تو کاملین کے ساتھ ہو اور اس نے کامل بننے کی پوری کوشش کی ہو مگر بعض خامیاں اس میں رہ گئی ہوں.ایسے شخص کے حق میں شفاعت ہرگز گنہ کو بڑھاتی نہیں بلکہ کامل ہونے کی خواہش کو تیز کرتی ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا.عرش سوم عرش کا لفظ تشریح طلب ہے.عرش کے متعلق لوگوں میں بہت کچھ اختلاف ہے.بعض لوگ اسے ایک جسم قرار دیتے ہیں.بعض اس کی حقیقت سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں اور صرف لفظ پر ایمان لانا کافی سمجھتے ہیں.عرش سے مراد صفات تنزیہیہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چشمۂ معرفت میں عرش کی حقیقت پر ایک لطیف بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ عرش درحقیقت صفات تنزیہیہ کا نام ہے جو ازلی اور غیر مبدل ہیں ان کا ظہور صفات تشبیہیہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے.اور وہ حامل عرش کہلاتی ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَ يَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ ثَمٰنِيَةٌ (الحاقّۃ:۱۸) قیامت کے دن تیرے رب کا عرش آٹھ (امور) اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے.یعنی آٹھ صفات کے ذریعہ سے ان کا ظہور ہورہا ہوگا.جیسا کہ اس وقت چار صفات سے ہوتا ہے.یعنی رب العالمین، رحمن، رحیم اور مالک یوم الدین کے ذریعہ سے.چونکہ صفات الٰہیہ کا ظہور فرشتوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے اس لئے یہاں ھُم کی ضمیر استعمال کی گئی ہے جس طرح بادشاہ اپنی جلالت شان کا اظہار عرش پر بیٹھ کر کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت ذوالعرش ہونے میں ہے.یعنی صفات تنزیہیہ کے ذریعہ سے جن میں کوئی مخلوق اس سے ایک ذرہ بھر بھی مشابہت نہیں رکھتی.عرش کوئی مخلوق چیز نہیں بعض لوگوں نے قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ دھوکا کھایا ہے کہ عرش مخلوق ہے.جیسے مثلاً یہ آیت ہے.اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ الایۃ ( المومن:۸ ) وہ کہتے ہیں کہ عرش کو جب کسی نے اٹھایا ہوا ہے تو معلوم ہوا وہ ایک مخلوق شئے ہے.لیکن یہ استدلال درست نہیں.حملِ عرش سے خلق عرش ثابت نہیں ہوتا کیونکہ حمل کے معنی صرف کسی مادی چیز کے اٹھانے کے ہی نہیں
Page 41
ہوتے بلکہ اس کے معنی اس کی حقیقت کے اظہار کے بھی ہوتے ہیں.چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہےاِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ١ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا(الاحزاب:۷۳ ) یعنی ہم نے اس امانت (شریعت) کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا.مگر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا.وہ یقیناً اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور نتائج سے بے پرواہ ہے.اس جگہ امانت کے اٹھانے کا ذکر ہے جس کے صرف یہ معنی ہیں کہ وہ اس پر عمل کرکے اس کے نتائج اور اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے.اسی طرح عرش کے اٹھانے کے یہ معنی ہیں کہ عرش کی حقیقت کو وہ ظاہر کرتے ہیں.اور یہ ظاہر بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات تنزیہیہ کو انسان نہیں پہنچ سکتا.سوائے اس طریق کے کہ اس کی صفات تشبیہیہ کے ذریعہ سے اس کا علم ہو.پس صفات تشبیہیہ صفات تنزیہیہ کی حامل ہیں.اور ان کی حقیقت سے انسان کو آگاہ کرتی ہیں.مثلاً خدا تعالیٰ کے سب خوبیوں کے جامع ہونے کا علم ہمیں صرف ان صفات کے ذریعہ سے ہوسکتا ہے جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں.جیسے اس کا رب ہونا، رحمن ہونا، رحیم ہونا، مَالِک یَوْمِ الدّین ہونا.اور یہ سب صفات تشبیہیہ ہیں.کہ انسانی اخلاق بھی ان کے ہم شکل پائے جاتے ہیں.اور پھر یہ صفات مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں.اور اس لئے ان کے جلوے عارضی ہوتے ہیں.لیکن اگر یہ صفات نہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ کے کامل الصفات ہونے کا کسی قسم کا ادراک بھی خواہ کتنا ہی ادنیٰ ہو ہمیں حاصل نہ ہوسکتا.رب العرش کے لفظ سے خلق عرش ثابت نہیں ہوتا ایک اور آیت بھی ہے جس سے عرش کے مخلوق ہونے کا استدلال کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے.قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ.اَلْاٰیَۃُ (المومنون:۸۷،۸۸ ) یعنی پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے.وہ ضرور جواب میں کہیں گے کہ اللہ.اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ رب العرش ہے تو معلوم ہوا کہ وہ عرش کا خالق ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ رب کے صرف خالق کے ہی معنی نہیں ہوتے بلکہ صاحب کے معنی بھی ہوتے ہیں.جیسے رب المال.پس رب العرش کے معنی ’’والے‘‘ کے ہیں یعنی عرش والا.جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے ذُوْالرَّحْمَۃِ (الکہف :۵۹) خدا تعالیٰ رحمت والا ہے.اور اسی طرح فرمایا ہےقُلْ لِلّٰہِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا (الفاطر:۱۱) حالانکہ رحمت اور عزت دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں.اور نہ ذوالرحمت کہنے سے رحمت مخلوق ثابت ہوتی ہے اور نہ لِلہِ الْعِزَّۃُ کہنے سے عزت مخلوق ثابت ہوتی ہے.پس رب العرش کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات تنزیہیہ بھی رکھتا ہے جس طرح کہ وہ صفات تشبیہیہ رکھتا ہے.صفات تشبیہیہ کی طرف سمٰوٰت کی پیدائش سے اشارہ کیا ہے.
Page 42
رَبُّ العَرش اور ذُو العَرش کے مفہوم میں فرق رہا یہ سوال کہ رب کا لفظ ذو یا صاحب کی جگہ کیوں استعمال کیا ہے سو اس میں بھی ایک حکمت ہے.اور وہ یہ کہ بعض نادان فلسفی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ علت العلل ہے.اس کی صفات اپنے طور پر اضطراری رنگ میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں.پس اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے مجموعہ کی نسبت رب کا لفظ استعمال کرکے جو تصرف پر دلالت کرتا ہے بتایا ہے کہ اس کی صفات اضطراری نہیں ہیں.بلکہ اس کے ارادے کے ماتحت ہیں جس رنگ میں اس کا کامل ارادہ اور بے عیب مشیت چاہتی ہے ان کا اظہار ہوتا ہے.پس اس لفظ کے استعمال سے اس نے ایک بہت بڑے اعتراض کا رد کر دیا ہے اور اسلامی عقیدہ کو ظاہر کر دیا ہے.کَانَ عَرْشُہٗ عَلَی الْمَآءِ سے بھی خلق عرش ثابت نہیں ہوتا تیسری آیت جس سے استدلال کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (ہود:۸) یعنی وہ خدا ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا ہے.اور اس کا عرش پانی پر ہے تاکہ وہ یہ امر ظاہر کرے کہ تم میں سے کون عمل میں سب سے بہتر ہے.چونکہ اس جگہ پانی پر عرش بتایا ہے اس لئے معلوم ہوا کہ عرش مخلوق ہے.اس جگہ پانی سے مراد حقیقی پانی نہیں ہو سکتا مگر یاد رکھنا چاہیے کہ پانی سے مراد اس جگہ پانی نہیں ہے کیونکہ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ سے پہلے عرش کا پانی پر ہونا درست نہیں.اس لئے کہ پانی تو سمٰوٰت وارض کا ایک جزو ہے.اور ان کی پیدائش کے بعد کی شئی ہے.اور اگر خَلَقَ السَّمٰوٰتِ کے بعد سمجھا جائے کہ مادی طور پر عرش پانی پر ہے تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں معلوم دیتا.ہمیں عرش پانی پرنہ نظر آتا ہے نہ اس کی کوئی علامت نظر آتی ہے.حالانکہ حکیم ہستی کا ہر کلام حکمت پر مشتمل ہوتا ہے اور جس چیز کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس سے ہمیں کوئی واسطہ ہے اس کے ذکر سے کیا فائدہ ہوسکتا ہے.اس کے بیان سے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا بھی کوئی اظہار نہیں ہوتا.کیونکہ اس کی حقیقت سے ہمیں بے خبر رکھا گیا ہے.پس نہ پانی سے مراد یہاں پانی ہے اور نہ عرش سے مراد کوئی مخلوق شئے.بلکہ پانی سے مراد الہامی زبان کے مطابق کلام الٰہی ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا عرش کلام الٰہی پر رکھا ہوا ہے.یعنی اس کی عظمت شان کو انسان نہیں سمجھ سکتا.مگر اس کی صفات تنزیہیہ جب کلام الٰہی کے ذریعہ سے تشبیہی رنگ اختیار کرتی ہیں تب انسان اس کی شان کا ایک اندازہ لگا سکتا ہے.اور اسی وجہ سے اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہم نے اس لئے کیا ہے کہ تاہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے.الہام کے نزول اور صفات تشبیہیہ کا تو تعلق انسان کے اعمال سے ہے.لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ایک نظر نہ آنے والا تخت اگر پانی پر رکھا ہوا ہو تو اس
Page 43
سے ہمارے اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا کوئی امتحان ہوسکتا ہے یا اس بیان سے ہم کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھاسکتے ہیں.بُطلان خَلقِ عرش عقلاً عقلاً بھی یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ عرش کوئی مخلوق چیز ہو کیونکہ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ دنیا کی پیدائش کے بعد خدا تعالیٰ کو کسی تخت کی ضرورت پیش آگئی.جو خدا ہمیشہ سے بغیر تخت کے حکومت کرسکتا تھا وہ آیندہ بھی بغیر تخت کے حکومت کرسکتا تھا اگر اظہار شان مراد ہو تو اظہار شان تو نظر آنے والی چیز سے ہوسکتی ہے جس کو انسان دیکھتا ہی نہیں نہ اس کی علامت ہی کو دیکھتا ہے اس سے اظہار شان ہو ہی نہیں سکتا.عرش سے مراد صفات تنزیہیہ ہونے کا ایک اور ثبوت اس امر کا ثبوت کہ عرش سے مراد صفات تنزیہیہ ہیں یہ آیت بھی ہے کہ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ١ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ (المومنون:۱۱۷ ) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کریم کو توحید باری کے ثابت کرنے میں ایک خاص تعلق ہے اور یہ امر ظاہر ہے کہ توحید کا اصلی اور حقیقی ثبوت اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہیہ ہی ہیں کیونکہ صفات تشبیہیہ میں مخلوق شریک ہوجاتی ہے.اور ایک کمزور عقل والے انسان کے لئے بہت سے افہام و تفہیم کی ضرورت پیش آتی ہے.اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا١ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا١ؕ اِنَّهٗ يَبْدَؤُا اسی کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے(یہ) اللہ (تعالیٰ) کا وعدہ ہے (جو) پورا ہو کر رہنے والا (ہے) الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وہ یقیناً مخلوق کو پیدا کر تاہےپھر اسے لوٹاتا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائےاور انہوں نے نیک (اور مناسب حال) کام بِالْقِسْطِ١ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ کئے انہیں اجرمیں کامل حصہ دے.اور جن لوگوں نے کفر( اختیار) کیا ان کے لئے ایک تو پینے کی ایک چیز عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ۰۰۵ یعنی کھولتا ہوا پانی ہوگااور( دوسرے) ایک دردنا ک عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے( چلے جاتے)تھے.حلّ لُغات.مَرْجِعٌ مَرْجِعٌ رَجَعَ سے نکلا ہے اور اس کا مصدر ہے اور اس کے معنی لوٹنے کے ہیں.
Page 44
دوسرا مصدر اس کا رجوع ہے جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے.بَدَ ءَ یَبْدَءُ بَدَءَ سے ہے.اور اس کے مختلف معنے ہیں.بَدَءَ بِالشَّیءِ اِفْتَتَحَہٗ.کسی چیز کا افتتاح کیا.بَدَءَ بِفُلَانٍ قَدَّمَہٗ فلاں شخص کی طرف پہلے متوجہ ہوا یا اس کا کام پہلے کیا.بَدَءَ الشَّیءَ اَخَذَ فِیْہِ اَوْقَدَّمَہُ فِی الْفِعْلِ.یعنی اس کام کو کرنے لگا یا اس کو اور کاموں سے پہلے کرنا شروع کیا.بَدَءَ الشَّیءَ أَنْشَاَہٗ وَاخْتَرَعَہٗ.اس چیز کو پیدا کیا اور اس کو ایجاد کیا.بَدَءَ اللہُ تَعَالیٰ الْخَلْقَ خَلَقَھُمْ مخلوق کو پیدا کیا.بَدَءَ مِنْ اَرْضِہٖ.خَرَجَ لِأَرْضٍ أُخْرَی وَتَغَرَّبَ اپنی زمین سے نکل گیا اور دوسرے ملکوں میں چلا گیا.(اقرب) خَلْقٌ اَلْخَلْقُ اَلْفِطْرَۃُ.پیدا کرنا.اَلنَّاسُ.لوگ (اقرب) اَلْمَخْلُوْقُ.خلق کے معنی مخلوق کے بھی ہوتے ہیں (مفردات) یُعِیْدُہٗ اَعَادَہٗ سے ہے اس کے معنے ہیں اَرْجَعَہٗ اسے لوٹا دیا.اَلْکَلَام کَرَّرہٗ جب کلام کے متعلق آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیںاسے دہرایا فُلَانٌ لَا یُعِیْدُ وَلَا یُبْدِئُی اِذَا لَمْ تَکُنْ لَہٗ حِیْلَۃٌ.کہتے ہیں فُلَانٌ لَا یُعِیْدُ وَلَا یُبْدیُ جب وہ بالکل بے بس ہو.(اقرب) صَلُحَ اَ لصَّالِحَاتُ صَالِحٌ کی جمع ہے.جو صَلح سے نکلا ہے.صَالِحٌ کے معنی ہوتے ہیں فساد سے پاک اور بامصلحت مناسب حال.قِسْطٌ اَلْقِسْطُ الْعَدْلُ.قِسْطٌ کے معنی عدل و انصاف کے ہوتے ہیں اور یہ ان مصادر میں سے ہے جنہیں صفت کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں.کہتے ہیں.رَجُلٌ قِسْطٌ انصاف والا آدمی اور یہ لفظ مفرد اور جمع دونوں کی صفت کے طور پر استعمال ہوسکتا ہے.اَلْحِصَّۃُ وَالنَّصِیْبُ اس کے معنی حصہ اور نصیب کے بھی ہوتے ہیں.اور نصف صاع کے وزن کو بھی قِسْطٌ کہتے ہیں.(اقرب) شَرَابٌ اَلشَّرَابُ کُلُّ مَا یُشْرَبُ مِنَ الْمَائِعَاتِ حَلَالًا کَانَ اَوْحَرَامًا (اقرب) ہر پینے کی چیز خواہ حلال ہو یا حرام.حَمِیْمٌ اَلْـحَمِیْمُ اَلْقَرِیْبُ الَّذِیْ تَہْتَمُّ بِاَمْرِہٖ.وہ قریبی جس کی ضروریات کے تم کفیل ہوتے ہو.اَلصَّدِیْقُ.دوست.اَحْمَاءُ اس کی جمع ہے اور اس کے معنی اَلْمَاءُ الْحَارُّ اور اَلْمَاءُ الْبَارِدُ کے بھی ہوتے ہیں.یعنی گرم پانی کے بھی ہوتے ہیں اور سرد پانی کے بھی.اس وقت اس کی جمع حَمَائِمُ آتی ہے.اسی طرح اس کے معنی اَلْقَیْظُ یعنی سخت گرمی اور اَلْمَطْرُالَّذِیْ یَأْتِی بَعْدَ اِشْتِدَادِ الْحَرِّ.وہ بارش جو سخت گرمی کے بعد آئے.اور اَلْعَرَقُ پسینہ بھی ہیں.(اقرب)
Page 45
تفسیر.موعود چیز کیا ہے وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا اصل میں وعدکم اللہ وعدا حقا ہے.فعل کو محذوف کرکے مصدر کو فاعل کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے.پس اس کے اصل معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک پختہ وعدہ کیا ہے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک تو انسان کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ اسے اپنی ظاہری آزادی کو دیکھ کر دھوکا نہیں کھانا چاہیے.آخر اس کا واسطہ اللہ تعالیٰ سے پڑے گا.دوسرے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی آخر میں کامیاب ہوں گے.کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرب کے لئے پیدا کیا ہے جیسا کہ فرمایا وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ(الذریات:۵۷) جن و انسان کو میں نے صرف اپنا عبد بننے کے لئے پیدا کیا ہے.اسی وعدہ کی طرف وَعْدَاللہِ حَقًّا میں اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ آخرکار سب انسان اللہ تعالیٰ کو پالیں گے اور نبیوں کی بعثت کی اصل غرض پوری ہوکر رہے گی.اِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ میں بھی دونو طرف اشارہ ہے اس طرف بھی کہ مرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ پھر زندگی دے گا اور اس طرف بھی کہ اللہ تعالیٰ نئی نئی مخلوق پیدا کرتا چلا جاتا ہے تاکہ نیکوں کے کام ضائع نہ ہوں.کیونکہ اگر کوئی خیر کا کام کرے اور اس کے بعد کوئی مخلوق نہ ہو تو اس کے کام سے کون فائدہ اٹھا سکتا ہے.لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور پچھلے لوگ پہلوں کے کام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پہلوں کے لئے ثواب کا موجب بنتے ہیں.صالح کے معنی اور ایک اہم نکتہ اس آیۃ میں جو عمل صالح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں فردی اور قومی ترقی کا ایک بہت بڑا نکتہ ہے.لوگ اس کا ترجمہ نیک عمل کرتے ہیں مگر اس کے معنی نیک عمل کے نہیں ہیں.بلکہ نیک اور مناسب حال عمل کے ہیں.یعنی عمل نیک بھی ہو اور ہو بھی موقع کے مطابق.مثلاً یہ نہ ہو کہ جہاد کے لئے جارہا ہو اور روزے رکھنے لگے.روزے ایک نیک عمل ہیں مگر جہاد کو جاتے وقت مناسب حال عمل نہیں ہیں.اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر فرمایا کہ آج بے روزہ، روزےداروں سے بڑھ گئے کیونکہ روزہ دار بوجہ روزہ کی تکلیف کے کیمپ کا انتظام نہ کرسکے اور بے روزوں نے فوراً کیمپ کو تیار کرلیا اور حق یہ ہے کہ فردی اور قومی ترقی ہر عمل خیر سے نہیں ہوتی بلکہ عمل صالح سے ہوتی ہے.مسلمانوں نے اس نکتہ کو نہیں سمجھا اور جس وقت اسلام کو سخت جہاد عقلی کی ضرورت تھی اس وقت ان کے مذہبی آدمی مصلے بچھا کر اور تسبیحیں پکڑ کر گھروں میں بیٹھے رہے اور ان اعمال سے غافل رہے جو کہ قومی ترقی کے لئے ضروری تھے.ان کا کام تھا کہ مسلمانوں میں عملی قوت پیدا کرنے کی کوشش کرتے اور ان کے اخلاق کو درست کرتے اور علوم جدیدہ کے حاصل کرنے کی ترغیب دیتے اور ان میں اتحاد عمل پیدا کرتے مگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نمازیں اور روزے اسلام اور مسلمانوں کو ہلاکت
Page 46
سے نہ بچا سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا کہ عمل صالح کے نتیجہ میں کامیابی ملتی ہے.اور ان لوگوں کے اعمال گو مذہب کے مطابق تھے مگر مناسب حال نہ تھے پس خدا تعالیٰ کا قانون توڑنے کی وجہ سے انہوں نے بھی اور دوسرے سب مسلمانوں نے بھی نقصان اٹھایا.هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ وہی ہے جس نے سورج کو ذاتی روشنی( والا) اور چاند کو نور( والا) بنایاہے اور ایک اندازہ کے مطابق مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ١ؕ مَا خَلَقَ اس کی منزلیں بنائی ہیں تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو.اس (سلسلہ )کو اللہ( تعالیٰ) نے اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ١ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ۰۰۶ حق ( وحکمت )کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے وہ ان آیات کو علم والے لوگوں کے لئے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے.حلّ لُغات.ضِیَآءٌ کو عربی محاورہ کے لحاظ سے نور سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے.دوسرے ضیاء اور ضوء اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں روشن ہوتی ہے اور نور کا لفظ اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کی روشنی غیر سے حاصل شدہ ہو (اقرب) ضِیَاءٌ ضَآءَ کا مصدر بھی ہے جس کے معنی روشن کر دینے یا روشن ہونے (متعدی و لازم) کے ہوتے ہیں.اور ضِیَاءٌ جمع بھی ہے ضَوْءٌ کی.جیسے سَوْطٌ کی جمع سِیَاطٌ (اقرب) نُوْرٌ کے معنی اس فرق کے علاوہ جو اوپر ذکر ہوچکا ہے یعنی وہ روشنی جو کسی چیز سے مکتسب ہو اور بھی کئی آتے ہیں.(۱) ظُلُمٰتٌ کے خلاف کا نام نُوْرٌ ہے اور کبھی یہ لفظ ضِیَاءٌ کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے.جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا (الاحزاب:۴۷ ) (۲) نورِ ضیاء کی شعاع کو بھی کہتے ہیں.یعنی جو چیز اپنی ذات میں روشن ہے اس کی روشنی کے انعکاس کو بھی نور کہتے ہیں.(۳) اور نور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے دوسری چیزیں نظرآنے لگ جائیں.یعنی مُنَوَّرٌ جیسے فرمایا.اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (النور:۳۶)(۴) ہر وہ چیز جس سے دوسری چیزوں کی پوری حقیقت کھل جائے.اس کو بھی نور کہہ دیتے ہیں.(۵) اور نور کے معنی وَسْمٌ کے بھی ہیں یعنی رونق کے.ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے چہرہ پر بڑا نور ہے.یعنی آثار برکت و عزت ہیں.(اقرب)
Page 47
ٍٍ تَفْصِیْلٌ:یُفَصِّلُ فَصّلَ کا مضارع ہے.جس کے معنی ہیں جَعَلَہٗ فَصُوْلًا مُتَمَایِزَۃً کسی چیز کو الگ الگ ٹکڑوں میں کر دیا.اور جب یہ لفظ کلام کے متعلق استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بَیَّنَہ یعنی اسے اچھی طرح کھول کر بیان کر دیا.اور فَصَّلَ اَجْمَلَ کی ضد بھی ہوتا ہے یعنی اس میں کسی قسم کا اخفاء یا اجمال نہ رہنے دیا.(اقرب) فرمایا هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَالْقَمَرَ نُوْرًا.وہ خدا ہی ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا یعنی ذَاضِیَاءٍ (روشنی والا) بنایا اور چاند کو نور یعنی ذَانُورٍ (نور والا) بنایا.تَقْدِیْرٌ قَدَّرَہُ اصل میں لام کے صلہ کے ساتھ آتا ہے.اور قَدَّرَلَہٗ بولتے ہیں.یعنی اس کے لئے یہ چیز اندازہ کر دی یا اس کے لئے یہ چیز مقرر کر دی تو قَدَّرَہٗ کے معنی قَدَّرَلَہٗ کے ہوں گے.یعنی چاند کے لئے منازل مقرر کر دیں.مگر کبھی کبھی محاروہ میں قَدَّرَ کا لفظ جَعَلَ اور صَیَّر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.اور یہ الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں.اور اس صورت میں ہم لام مقدر نہ نکالیں گے.بلکہ جیسے وہاں ذَاضِیَاءٍ اور ذَا نُورٍ مراد ہے اسی طرح یہاں ذَامَنَازِلَ مراد ہوگا.یعنی اس (ذَامَنَازِلَ ) کو جَعَلَ کا مفعول ثانی قرار دیں گے.اور معنی یہ ہو جائیں گے کہ ان میں سے ہر ایک کو منزلوں والا بنایا ہے.ہٗ کی ضمیر دونوں طرف جاتی ہے.یعنی سورج اور چاند دونوں کے لئے منازل مقرر ہیں.سورج بھی درحقیقت حرکت کرتا ہے.گو زمین کے گرد گول حرکت نہیں کرتا جیسا کہ پہلے زمانے کے لوگ سمجھتے تھے.تحقیقات جدیدہ سے یہ ثابت ہے کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھومتی ہے لیکن تاہم سورج اپنے سیاروں سمیت کسی طرف کو جارہا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرکت کتنی لمبی ہے.ممکن ہے کہ یہ حرکت ایک نہایت وسیع دائرہ کی صورت میں ہو جس کا اندازہ لاکھوں سالوں میں بھی نہ کیا جاسکتا ہو.تفسیر.کرّوں کی حرکت ہی مقدار فعل اور زمانہ کے علم کا ذریعہ ہے فرمایا لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ.دیکھو یہاں کیسی لطیف بات بیان فرمائی ہے.ہر حرکت کا اندازہ کرنے کے لئے اس کے مقابل کی چیزوں کی نسبت ہی معیار ہوا کرتی ہے.مثلاً ہم ریل میں سفر کریں اور جس رفتار سے ریل چل رہی ہو اسی رفتار سے تمام اردگرد کی چیزیں بھی حرکت کریں.تو ہمیں ذرا بھی محسوس نہ ہوگا کہ ہم نے حرکت کی ہے.بلکہ جہاں بیٹھے تھے وہیں اپنے آپ کو سمجھیں گے.تو گویا چلنے کی کیفیت نسبت ہی سے معلوم ہوتی ہے.اگر نسبت موجود نہ ہوتی تو کیفیت بھی معلوم نہ ہوسکتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہےلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ کہ ہم نے سورج اور چاند کی منازل اس لئے مقرر کی ہیں تاکہ تم عدد سنین اور حساب کو جان سکو.یعنی ان خارجی وجودوں کی حرکت کو دیکھ کر معلوم کرسکو کہ تم پر ایک زمانہ گزر گیا ہے اور تم اس جگہ پر نہیں رہے جہاں پہلے تھے.اگر یہ فرق نہ ہوتا یعنی زمین سے باہر کوئی اور کرہ
Page 48
نہ ہوتا جو حرکت کرتا اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں نظر آتا تو کبھی بھی ہم میں زمانہ کا احساس پیدا نہیں ہوسکتا تھا.اور اگر وہ کرہ خود ایک خاص قانون کے ماتحت حرکت نہ کرتا یا اس کے گرد دوسرے کرہ جات ایک خاص قانون کے ماتحت حرکت نہ کرتے تو وقت کے احساس کو خاص اندازوں میں تقسیم کرنا ناممکن ہو جاتا.پس تمام تاریخ اور حساب کا معاملہ سورج اور چاند سے تعلق رکھتا ہے.ایک کی اپنی گردش سے اور دوسرے کے گرد دوسرے سیاروں کی گردش سے.چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور اس سے مہینوں اور ہفتوں کاا ندازہ ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین گھومتی ہے اور اسی طرح اس کے سامنے گھومتی ہے.اس سے دنوں اور سالوں کا اندازہ ہوتا ہے.حساب کا تعلق بھی سیاروں کی گردش سے نہایت گہرا ہے.ایک لطیف نقطہ اس میں ایک لطیف مذہبی نکتہ بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ سنین سے محنت کے اندازے معلوم ہوتے ہیں.اور حساب سے نتیجہ کا پتہ لگتا ہے.ہر کام میں دو اندازے ہوا کرتے ہیں.اول یہ کہ کتنی محنت کی دوسرے یہ کہ کیا نتیجہ نکلا ہے.اگر یہ دو اندازے مدنظر نہ رکھے جائیں تو لوگ مقابلہ میں پورے نہیں اترسکتے.مثلاً ایک شخص ایک سال میں ایک کپڑا بنتا ہے اور دوسرا دو گھنٹے میں تو پہلا دوسرے کا مقابلہ نہیں کرسکتا.غرض محنت اور نتیجے کے توازن سے ہی کسی کام کی کامیابی یا ناکامی کا حال معلوم ہوتا ہے اور یہ دونوں باتیں سورج اور چاند سے متعلق ہیں.پھر جس طرح جسمانی طور پر سورج اور چاند مقرر ہیں تاکہ عدد سنین اور حساب کو ظاہر کریں اسی طرح روحانی طور پر بھی سورج اور چاند ہوتے ہیں یعنی انبیاء.وہ مذہبی طور پر عددسنین و حساب ظاہر کرتے ہیں.یعنی ان کے ذریعہ سے ہی روحانی دنیا میں محنت اور اس کے نتائج کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وقت کی قیمت قوم کو معلوم ہوتی ہے.نبیوں کے بغیر مذہبی دنیا میں کوئی حقیقی احساس پیدا ہی نہیں ہوسکتا.اور روحانی ترقیات کے اندازوں سے دنیا بالکل بے خبر رہتی ہے.بعینہٖ جس طرح سورج اور چاند کے بغیر ظاہری دنیا وقت کے احساس سے اور اس کے اندازوں سے واقف نہیں ہوسکتی.چوڑھوں کو دیکھ لو یا اسی قسم کی دوسری ادنیٰ قوم کو.ان میں انسانی پیدائش کی غرض و غایت کا احساس ہی مٹ گیا ہے.ہزاروں سال سے وہ اس حالت میں ہیں لیکن روحانیت بلکہ دنیوی ترقی تک کا احساس ان میں نہیں ہے.انہیں کہا بھی جائے تو کہتے ہیں کہ قسمت ہے گویا وہ ایک نہ ختم ہونے والی رات کے اثر کے نیچے غافل پڑے ہیں.پس انبیاء دنیا کے لئے بطور سورج کے اور بطور چاند کے ہوتے ہیں.وہ فطرۃ انسانی کی مخفی ترقی کو اور اس کے ارتقاء کو ظاہر کرتے ہیں.اور ان سے علم حاصل کرکے لوگ روحانی دنیا کی ترقی کی خبر پاتے اور اس کے مطابق عمل کرتے اور نتائج پیدا کرتے ہیں.اور ان کے بغیر روحانی دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہوسکتی.
Page 49
اِلَّا بِالْحَقِّ یعنی اس نے زمین و آسمان کو فضول اور یونہی بے فائدہ نہیں پیدا کیا.اس کو شوق نہ تھا کہ کرہ پر کرہ بناتا چلا جاتا.اس نے یہ سب کچھ پائدار مقصد کے لئے پیدا کیا ہے.پس جسمانی سورج کی طرح روحانی سورج بھی چاہیے تھا.يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.وہ اپنی آیات بیان فرماتا ہے اس سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس نظام عالم کا علم رکھتے ہیں.جو سورج چاند کے منازل کو جانتے ہیں.کیونکہ جس شخص کو ان تغیرات کا علم ہی نہیں وہ عددسنین اور حساب کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ قاعدہ کی بات ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا.اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا.جب تک روحانی علوم کو نہیں سیکھتا.اور ان کی حقیقت پر غور نہیں کرتا.اِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو کچھ اللہ (تعالیٰ) نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ۰۰۷ ( اس میں) متقی لوگوں کے لئے یقیناًیقیناًبہت سے نشان ہیں.حلّ لُغات.اِخْتَلَافٌ اِخْتِلَافٌکے دو معنے ہوتے ہیں.(۱) ضِدُّ اتَّفَاق.یعنی عدم اتفاق (۲) اِخْتَلَفَ زَیْدٌ عَمْرًا کَانَ خَلِیْفَتَہٗ.زید عمر کا خلیفہ ہوا.اس آیت میں پچھلے معنی ہیں.یعنی رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا.تفسیر.یَعْلَمُوْنَ کے مقابل پر یَتَّقُوْنَ لانے کی وجہ پہلی آیت اور اس آیت میں یَتَّقُوْنَ اور یَعْلَمُوْنَ کا فرق کر دیا گیا ہے.پہلی آیت میں بتلایا تھا کہ علم والے لوگوں کے لئے نشان ہیں اور اس میں فرمایا ہے کہ تقویٰ رکھنے والوں کے لئے آیات ہیں.اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ دن اور رات کے اختلاف کو جانتا تو ہر شخص ہے ایک چوہڑے کو بھی معلوم ہے کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے.مگر اس سے فائدہ اٹھانا تقویٰ پر موقوف ہے.متقی ہی اس تغیر اور اختلاف سے فائدہ اٹھاتا ہے.مگر پہلی آیت میں منازل شمس و قمر کا ذکر ہے اور ان کا جاننا علم سے تعلق رکھتا ہے.پس فائدہ بھی عالم ہی اٹھاسکتا ہے.اس لئے وہاں یَعْلَمُوْنَ رکھا اور اس جگہ یَتَّقُوْنَ فرمایا.اور فرماتا ہے کہ رات اور دن بے شک دونوں مفید چیزیں ہیں اور ان کا سلسلہ بھی چل رہا ہے کبھی رات آتی ہے اور کبھی دن.یہی
Page 50
حال قوموں کا ہوتا ہے کہ ان پر کبھی رات آتی ہے اور کبھی دن.مگر جس قوم پر رات ہی رات رہے وہ ترقی نہیں کرسکتی.اور اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ کسی قوم پر ہمیشہ دن ہی دن رہے.کیونکہ انسان اپنے اعمال میں کبھی یکساں نہیں رہ سکتا.جوں جوں نبیوں سے بعد ہوتا جائے گا اور زیادہ زمانہ گزرتا جائے گا تاریکی ہوتی جائے گی جیسے سورج سے دور ہونے کی وجہ سے ہم پر رات پڑ جاتی ہے ورنہ سورج کہیں چلا نہیں جاتا.پس کوئی قوم اس بات سے خوش نہ ہوجائے کہ رات اور دن کا آنا جانا لازمی ہے.کیونکہ روحانی دنیا میں بھی گو رات کا آنا لازمی ہے مگر اس کا دور کرنا بھی انسان کے اختیار میں ہے.بے شک ترقی اور تنزل قوموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں.مگر تنزل کو دور کرنا اور ترقی کے حصول کے لئے کوشش کرنا بھی ضروری ہے.زندگی پیدا کرنے کے لئے جدوجہد کا چھوڑ دینا اور رات کو ایک طبعی اور خودبخود دور ہوجانے والی چیز سمجھ لینا غلطی ہے.متقی انسان رات کے وقت کو دیکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی قوم پر سورج چڑھے.اور نبی آکر یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے دروازے کھولو اور سورج چڑھا لو.اس بات پر مطمئن نہ ہوجاؤ کہ تنزل قوموں کے ساتھ لگا ہی ہوا ہے.کسب کا تعلق نہار سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ (الانعام:۶۱ ) پس اگرچہ رات قدرتی اور مفید چیز ہے مگر بغیر دن کے مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا.تمام کام دن سے تعلق رکھتے ہیں.کانوں کا کھودنا، زراعت، تجارت وغیرہ سب کسب دن سے ہی تعلق رکھتے ہیں.اور وہ سورج سے پیدا ہوتا ہے پس اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبوں سے فرماتا ہے کہ تم بھی اس روحانی سورج (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) سے تعلق پیدا کرو تا تمہاری قوم پر دن چڑھے اور رات دور ہو.کیونکہ سورج سے تعلق پیدا کئے بغیر یہ بات ناممکن ہے.اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور اس ورلی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس پر انہوں نے اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَۙ۰۰۸ اطمینان پکڑ لیا ہے اور (پھر) جو لوگ ہمارے نشانوں (کی طرف) سے غافل ہو گئے ہیں.ان (سب) کا ٹھکانا
Page 51
اُولٰٓىِٕكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ۰۰۹ ان کی (اپنی )کمائی کی وجہ سے یقیناً (دوزخ کی) آگ ہے.حلّ لُغات.رَجَاءٌ یَرْجُوْنَ رَجَاءٌ میں سے فعل مضارع ہے.عربی زبان میں رَجَاءٌ کا لفظ دو معنوں میں مستعمل ہوتا ہے.أَمَّلَ بِہٖ.اس کی امید رکھی.خَافَہٗ.اس سے ڈرا.(اقرب) عام طور پر امید کے معنوں میں آتا ہے.اور خوف کے لئے کم.مگر آتا ضرور ہے.لِقَآءٌ لِقَاءٌ لَقِیَ یَلْقٰی اور لَاقٰی یُلَاقِیْ ہر دو باب کا مصدر ہے.پہلے باب میں اس کے معنی ہوں گے اِسْتَقْبَلَہٗ آگے ہو کر ملا.رَاٰہ اسے دیکھا.اور دوسرے باب میں اس کے معنے ہوں گے قَابَلَہٗ اس کے آمنے سامنے ہوا.(اقرب) وَفِی الْمَغْرِبِ وَقَدْ غَلَبَ الّلقَاءُ عَلَی الْـحَرْبِ اور مغرب میں لکھا ہے کہ لِقَاء کا لفظ زیادہ تر جنگ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے (اقرب) اِطْمَئَنَّ اِلَی کَذَا.سَکَنَ وَاٰمَنَ لَہٗ.ٹھہر گیا اور مطیع ومنقاد ہوگیا.(اقرب) اٰوٰی مَأْوٰی اٰوٰی یَأْوِیْ مَأْوًی سے نکلا ہے اور اس کا اسم ظرف ہے.اوٰی اِلیٰ کَذَا اِنْضَمَّ اِلَیْہِ.اس سے لپٹ گیا.(مفردات) مَأْوٰی اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان اترے اور اسے اپنی حفاظت کی جگہ سمجھے.کیونکہ ایسی جگہ سے انسان گویا لپٹ جاتا ہے.کَسَبَ الشَّیْءَ.جَمَعَہٗ اس چیز کو جمع کرلیا.اَلْاِثْمَ تَحَمَّلَہٗ گناہ کو جان بوجھ کر اختیار کرلیا.مَالًا وَعِلْمًا طَلَبَہٗ وَرَبّـحَہٗ مال یا علم کو طلب کیا اور نفع بخش بنایا.(اقرب) تفسیر.قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ وہ ایسے الفاظ استعمال فرماتا ہے جو باوجود اختصار کے وسیع مطالب پیدا کردیتے ہیں.اور چونکہ اس غرض کو پورا کرنے میں عربی زبان بہت کچھ ممد ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو قرآن کریم کی زبان ہونے کا شرف بخشا ہے.اس آیت میں دیکھو کہ عذاب میں مبتلا ہونے کے اسباب کو لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں رجاء کے دو معنے ہیں امید اور خوف اسی طرح لقاء کے دو معنی ہیں.شوق سے آگے ہوکر ملنا.یا جنگ و جدال.اب فطرۃ انسانی پر غور کرکے دیکھ لو تمام انسانی ترقیات یا امید سے وابستہ نظر آئیں گی یا خوف سے.کامل عمل یا خوف سے پیدا ہوتا ہے یا امید سے.بعض لوگ اس لئے کام کرتے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے.اور بعض اس لئے کہ وہ دکھ نہ پائیں.قرآن مجید نے ایک ہی فقرہ میں دونوں فطرتوں کو مخاطب کرلیا ہے اور فرماتا ہے کہ اے وہ فطرۃ جو امید کے لئے کام کرتی ہے تو ہمارے ملنے
Page 52
کی امید کیوں نہیں رکھتی.اور اس امید کے مطابق کیوں عمل نہیں کرتی.اگر تو امیدسے دور رہے گی تو بجائے ترقی کرنے کے تنزل کے عمیق گڑھوں میں گر جائے گی.اور انہی الفاظ میں دوسری فطرت کو بھی مخاطب کرلیا ہے کہ اے وہ فطرت جو ڈر سے کام کیا کرتی ہے تو ہماری سزا سے بچنے کے لئے کیوں کوشش نہیں کرتی.اور اس سے کیوں نہیں ڈرتی.ورنہ یاد رکھ کہ ایسے ایسے ابتلاء تیرے سامنے ہیں کہ جن کی برداشت تیری طاقت سے زیادہ ہوگی گویا قرآن مجید نے ایک ہی لفظ سے پیار سے ماننے والی اور خوف سے اطاعت کرنے والی دونوں فطرتوں کی تسلی کردی.دنیوی ترقی اور اسلام کا نقطہ نگاہ اس آیت میں رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا فرماکر دنیوی ترقیات کے متعلق اپنا نقطۂ نگاہ واضح کر دیا ہے.کہ اسلام دنیوی ترقیات کا مخالف نہیں.جس امر کا وہ مخالف ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا پر اکتفا کرلے اور خدا تعالیٰ کی محبت اس کے دل سے نکل جائے.دوسرے یہ کہ وہ دنیا کے حصول کے بعد مزید ترقی کا خیال ترک کر دے اور اس پر ٹھہر جائے اور اطمینان پکڑ لے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے.اطمینا ن کے معنی سکون کے ہوتے ہیں یعنی حرکت کے ترک کر دینے کے.مطمئن اسے کہتے ہیں جو خیال کرتا ہے کہ اس نے اپنے مقصد کو پالیا.اور اس نے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا.اور آگے چلنا اس نے بند کر دیا.اور مزید ترقی کی کوششیں اس نے چھوڑ دیں.اصل بات یہ ہے کہ رضا دو قسم کی ہوتی ہے.ایک رضا وہ ہوتی ہے جس کے بعد انسان کو آئندہ کوشش کا بھی خیال رہتا ہے.وقتی طور پر تو وہ راضی ہو جاتا ہے لیکن آئندہ زیادہ کے حصول کی کوشش کا ارادہ اس میں باقی ہوتا ہے.دوسری وہ رضا جس کے بعد آئندہ کسی کوشش کا خیال اس کے دل میں نہیں رہتا.اس جگہ وَاطْمَأَنُّوْا بِہَا فرما کر دوسری رضاء کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ جو دنیا پر اطمینان کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے اور ہمیں بھول جاتا ہے اور اخروی ترقیات کو نظرانداز کر دیتا ہے وہ ہمارے الزام کے نیچے ہے نہ کہ مجرد دنیوی ترقیات کرنے والا.کیونکہ دنیوی ترقیات تو خود انعامات الٰہیہ میں سے ہیں.جیسا کہ اللہ تعالیٰ دعا سکھاتا ہےرَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرۃ:۲۰۲).جو دنیوی ترقیات اخروی ترقیات سے وابستہ ہوں وہ انعامات الٰہیہ میں سے ہیں.اور ان کو مانگنا مومن کے فرائض میں سے ہے.اس سے آگے چل کر مضمون کو اور بھی واضح کر دیا ہے او ر وَالَّذِیْنَ ھُمْ عَنْ اٰیَاتِنَا غَافِلُوْنَ فرماکر بتایا ہے کہ یہ لوگ جن پر ہم ناراض ہیں وہ ہیں کہ جو دنیا میں اس قدر منہمک ہوجاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلام اور اس کے نبیوں اور اس کی شرائع کی تحقیر کرنے لگ جاتے ہیں.اور ان سے آنکھیں بند کرلیتے ہیں.اور اس طرح اپنی ہدایت کے دروازے بند کرلیتے ہیں.کیونکہ ان کے دلوں کے زنگ خدا ہی کی ہدایت سے دور ہوسکتے تھے.وہ اپنے آپ کو
Page 53
ان سے بالا سمجھنے لگ جاتے ہیں.اور اس طرح آئندہ کے لئے بھی ان کے ہدایت پانے کی امید نہیں رہتی.گناہ اورسزا کی حقیقت تیسرا نکتہ جو اس آیت میں یاد رکھنے کے قابل ہے یہ ہے کہ اس میں گناہ اور سزا کی حقیقت پر ایک لطیف روشنی ڈالی گئی ہے.گنہ کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی گناہ جس کی سزا ملتی ہے وہ ہے جو مکسوب ہو.اور کسب کے معنی جیسا کہ لغت سے ثابت کیا جاچکا ہے جمع کرنے اور جان بوجھ کر کرنے کے ہیں.پس کسب کے لفظ سے دو اشارے کئے گئے ہیں ایک تو یہ کہ گناہ گار وہ ہے جو جان بوجھ کر گناہ کی آلائش میں گرتا ہے.اگر خطاء اور نسیان سے کوئی برا فعل انسان سے صادر ہوجاتا ہے تو وہ حقیقی گنہ نہیں اور ایسا انسان شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں گنہ گار نہیںکہلائے گا اور دوسرا اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ گناہ گار کے لئے ضروری ہے کہ وہ گناہ کو جمع کرے یعنی تواتر سے گناہ میں مبتلا ہو.اگر تواتر نہ ہو یعنی انسان گودیدہ و دانستہ ہی گنہ کرے مگر اس کے فعل کے بعد پشیمان ہوکر اسے چھوڑ دے اور توبہ کرے تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا.کیونکہ کسب کے معنوں میں جمع کرنا بھی شامل ہے.اور تواتر پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے.پس ان معنوں کی رو سے اسلامی شریعت میں سزا کے قابل مجرم وہی ہوگا جو دیدہ و دانستہ جرم کرے اور بعد میں اس سے تائب نہ ہوا ہو.چنانچہ ایک دوسری آیت میں اس کی تشریح ان الفاظ میں ہے اَلَّذِیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ کَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّکَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَۃِ (النجم:۳۳) جو لوگ بڑے گناہوں اور کھلے عیبوں سے بچتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ مرتکب ہو کر بعد میں اس کو چھوڑ بیٹھے ہوں (انہیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا).تیرا رب یقیناً وسیع مغفرت والا ہے.جہنم مجرموں کے لئے پناہ کی جگہ ہے سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ.ان کا مَأْوٰی نار ہوگا.مَأْویٰ جیسا کہ بتایا گیا ہے پناہ کی جگہ اور اس مقام کو کہتے ہیں جس سے انسان چمٹ جاتا ہے.اب یہ عجیب بات ہے کہ آگ کو پناہ کی جگہ اور چمٹ رہنے کا مقام قرار دیا جائے.مگر تھوڑے سے غور سے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس جگہ الٰہی سزا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ کی سزا دکھ دینے کے لئے نہیں بلکہ علاج کے لئے ہوتی ہے.اور جس طرح علاج کی تکلیف کو انسان برا سمجھتا ہے مگر آخر اسی میں اپنی بہتری سمجھ کر اسے قبول کرتا ہے اسی طرح جب عذاب کی حقیقت کا انکشاف گناہ گاروں پر پوری طرح ہوجائے گا تو وہ اس نار کو جس میں ان کو ڈالا جائے گا اپنا ماویٰ خیال کریں گے یعنی حقیقی عذاب سے نجات کا ذریعہ جو کہ خداوند تعالیٰ کی ناراضگی اور اس سے دوری ہے.پس ماویٰ کا لفظ استعمال کرکے بتایا ہے کہ عذاب دکھ میں ڈالنے کا ذریعہ نہیں بلکہ پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور صرف وہی ایک ذریعۂ نجات و تطہیر ہے.
Page 54
عذاب آخرۃکو نار سے تعبیر کرنے کی وجہ عذاب اخروی کا نام نار اس لئے رکھا گیا ہے کہ دنیا دو مظاہر کا مجموعہ ہے ناری اور نوری.خدا تعالیٰ سے تعلق نور کی طرف لے جاتا ہے جو ٹھنڈک اور خوشی کا موجب ہوتا ہے اور دنیا کی طرف جھک جانا نار کی طرف لے جاتا ہے.کیونکہ بدی ایک آگ ہے جو اسے اختیار کرلیتا ہے اس کے لئے اسی کے مشابہ مقام تجویز کیا گیا ہے.اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک (اور مناسب حال) عمل کئے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے بِاِيْمَانِهِمْ١ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ۰۰۱۰ (کامیابی کے راستہ کی طرف )ہدایت دے گا (اور) آسائش والی جنتوں میں انہی کے (تصرف کے) نیچے نہریں بہتی ہوں گی.حلّ لُغات.تَـحْتَ تَـحْتَکا لفظ فَوْقَ کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے.یعنی اس کے معنی نیچے کے ہوتے ہیں اور اَسْفَلَ کا لفظ بھی نیچے کے معنوں میں آتا ہے.مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے.اَسْفَلَ ا س کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا نچلا حصہ ہو مگر تحت اسی چیز کے نچلے حصہ کو نہیں کہتے بلکہ اس جہت کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کے نیچے کی ہو.ہاں کبھی کبھی اسفل کا لفظ تحت کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے.نیز یہ لفظ رذیل اور ماتحت لوگوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.آخری زمانہ میں مزدوروں کے سرمایہ داروں پر حکومت کرنے کی پیشگوئی چنانچہ حدیث میں آیا ہے لَاتَقُوْمُ السَّاعَۃُ حَتّٰی یَظْہَرَ التَّحُوْتُ (کنز العمال کتاب القیامۃ باب فی اشراط الساعۃ الکبریٰ).یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک غرباء اور مزدور لوگ غالب آکر حکومتوں پر قابض نہ ہوجائیں.قرب قیامت کا زمانہ مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے پس اس حدیث میں بالشویک حکومت کی طرف اشارہ ہے.یعنی مسیح موعودؑ کے کامل ظہور کا زمانہ نہ آئے گا جب تک کہ محنتی لوگ سرمایہ داروں پر اور مزدور لوگ حکومتوں پر غالب نہ ہوجائیں گے.یعنی وہ بادشاہ نہ بن جائیں گے.اور سرمایہ دار ان کے ماتحت نہ ہوجائیں گے.ان معنوں کے رو سے مِنْ تَحْتِھِمُ الْاَنْھَارُ کے یہ معنی ہوئے کہ ان کے قبضہ میں نہریں ہوں گی اور وہ ان کی اپنی ملکیت ہوں گی.کیونکہ عمل ان کے
Page 55
پنے تھے جس طرح اس دنیا میں افسران انہار زمینداروں کو لوٹتے ہیں یا انہیں سرکاری ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں وہاں ایسا نہ ہوگا.بلکہ نہریں ان کی اپنی ملکیت ہوں گی.نَعِیْمٌ اَلنَّعِیْمُ عام طور پر لوگ اس کے معنی غلط سمجھتے ہیں.اور وہ اسے نعمت کی جمع قرار دیتے ہیں.حالانکہ ایسا نہیں ہے.بلکہ اَلنَّعِیْمُ کے معنی (۱) عطیہ (اقرب) یا (۲) اَلنِّعْمَۃُ الْکَثِیْرَۃُ یعنی بہت سی نعمت کے ہوتے ہیں.(مفردات) تفسیر.ایمان کے ساتھ عمل کی شرط اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اصل ہدایت ایمان کے سبب سے ملتی ہے.خالی عمل کچھ چیز نہیں.جب تک اس کے ساتھ دل کی اصلاح نہ ہو.ایک شخص چوری کا پورا ارادہ رکھتا ہو مگر اسے چوری کا موقع نہ ملے تو وہ دیانت دار نہیں کہلا سکتا.اسی طرح دل تو غیراللہ کے خوف سے پر ہو مگر ظاہر میں اسے سجدہ نہ کرے تو وہ شخص موحد نہیں کہلا سکتا.بعض نادان یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام عمل پر زور نہیں دیتا.بلکہ صرف ایمان کو پیش کرتا ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں.اسلام جس بات پر زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل کے ساتھ دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے.اگر دل پاک نہیں اور عمل کا ساتھ نہیں دیتا تو ایسا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا.اور کون عقل مند اس امر کا انکار کرسکتا ہے کہ اصل پاکیزگی دل کی اور خیالات کی پاکیزگی ہے.جب دل پاک ہوجاتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اعمال اس کی اتباع نہ کریں.یہ تو ہوسکتا ہے کہ انسان لوگوں کے خوف سے عمل اور قسم کے کرے مگر یہ نہیں ہوسکتا ہے کہ انسان لوگوں کے خوف سے اپنے خیالات کو بدل لے.دل پر دوسرے انسانوں کا تصرف نہیں ہوتا.زبردست بادشاہوں کے قبضہ سے بھی دل بالا ہے.پس ایسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مدار رکھا ہے جو خود انسان کے قبضہ میں ہے.اور دوسرے لوگوں کا اس میں دخل نہیں.جزا ایمان کے مطابق ہو گی بِـاِیْـمَانِہِمْ کہہ کر اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جزاء ایمان کے مطابق ہوگی.یعنی ظاہری عمل میں گو وہ شخص برابر ہوں لیکن وہ اخلاص اور وہ محبت جو عمل کے پیچھے ہے اس سے جزاء میں فرق آجائے گا.یہ بھی ایک زبردست نکتہ ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کو تم پر فضیلت اس چیز کے سبب سے ہے جو اس کے دل میں ہے.ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اور روزے بھی زیادہ رکھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو ایک دوسرا شخص جذب کرلیتا ہے اس کی وجہ اس کے دل کی حالت ہوتی ہے.حقیقی پاکیزگی اور اخلاص جسے زیادہ حاصل ہوتا ہے اس کے تھوڑے عمل زیادہ فوائد کو کھینچ لیتے ہیں.درحقیقت اس شخص کے سب اعمال ہی عبادت بن جاتے ہیں.کیونکہ اس کے بظاہر دنیوی نظر آنے والے اعمال بھی خدا ہی کے لئے ہوتے ہیں.
Page 56
اور بنی نوع انسان کی ہمدردی اس کی ہر حرکت کا موجب ہوتی ہے.دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ١ۚ وَ ان (جنتوں) میں (خدا تعالیٰ کے حضور) ان کی پکار اے اللہ (ہم) تیری تسبیح( کرتے ہیں) ہوگی.اور( ان کی) اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَؒ۰۰۱۱ ایک دوسرے کے لئے دعا( تمہارے لئے ہمیشہ کی) سلامتی (ہو)ہوگی اور ان کی دعا کا آخری حصہ یہ ہوگا کہ ہر ( قسم کی) تعریف اللہ( تعالیٰ) ہی کو سزاوارہے.حلّ لُغات.دَعْوٰی دَعْویٰ پکار اور آواز کے معنوں میں استعمال ہوتاہے.تَحِیَّۃٌ کے معنی ہیں سلام.جیسے ہم آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں.بقا.السّلامۃ من الاٰفات.بلاؤں سے محفوظ رہنا.اَلْمُلْکُ بادشاہت یہ معنی اس وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں کہ جب کوئی شخص بادشاہ بنایا جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے نَالَ فُلَانٌ التَّحِیَّۃُ کہ فلاں شخص کو سلام کا مقام حاصل ہو گیا ہے یعنی وہ سلام جو بادشاہوں سے مخصوص تھا.اور وہ اَبَیْتَ اللَّعْنُ کے الفاظ تھے.جاہلیت کے زمانہ میں جو بادشاہ ہوتا اس کے ساتھ کلام کرتے وقت یہ الفاظ بولے جاتے تھے جن کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ تجھے ہر قسم کے اعتراض اور شکست سے بچائے.اَلتَّحِیَّۃُ مِنَ اللہِ: اَلْاِ کْرَامُ وَالْاِحْسَانُ.یعنی جب کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی مخلوق کو تحیہ حاصل ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسے عزت دی گئی ہے.اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے.(اقرب) سَلَامٌ.سَلَامٌ کے کئی معنی ہیں.اِسْمٌ مِنَ التَّسْلِیْمِ.باب تفعیل سے اسم مصدر ہے اور اس کے معنی سلامتی دینے کے ہیں.اِنْقِیَادٌ یعنی فرمانبرداری.سلام خدا کا نام بھی ہے.کیونکہ وہ تمام عیبوں اور نقصوں سے پاک ہے.(الحشر ع۴).(اقرب) تفسیر.جنّت میں یہ کلمات علم و بصیرت کی بنا پر صادر ہوں گے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن جب اخروی انعامات پائیں گے تو پہلے تو بے اختیار ان کے منہ سے سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّ نکلے گا.یعنی اے اللہ !تو ہر عیب سے پاک ہے.(۲) دوسرے وہ آپس میں سلام کریں گے یا ان کو خدا کی طرف سے سلام ملے گا.(۳) تیسرے ان کا آخری کلام یہ ہوگا کہ وہ اَلْحَمْدُلِلہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَکہیں گے.یہ جو فرمایا کہ وہ جنت میں
Page 57
جاتے ہی سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّ کہیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان پر حقائق اشیاء کھل جائیں گے.مومن دنیا میں سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّکہتا ہے مگر اس جگہ یہ صرف اعتقادی رنگ میں ہوتا ہے.وہ کئی دفعہ آم کا چھلکا پڑا دیکھتا ہے اور اسے فضول سمجھتا ہے.یا رات کو ایک کیڑاا س کے بستر میں آ گھستا ہے وہ اس کی حکمت نہیں جان سکتا.لیکن تاہم وہ سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّکہتا ہے.ایسا ہی وہ جنگل میں جھاڑیاں دیکھتا ہے جن میں بعض کانٹے دار ہیں اور بعض بے کانٹے.ایسا ہی بعض درخت، ان کے پتے ،ان کی شاخیں دیکھتا ہے اور ان کی حکمت نہیں جانتا.وہ یہ سمجھ کرکہ کوئی حکمت ہوگی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے.کیونکہ ہم اس دنیا میں قیاس کرلیتے ہیں کہ جب بعض چیزوں میں اس کی حکمت نظر آتی ہے تو باقی چیزوں میں بھی ضرور حکمت ہوگی.نیز خدا کا سچا کلام بتلاتا ہے کہ خدا بے عیب ہے.ہم ایمان لاتے ہیں.اگرچہ کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کی حکمت ہمیں معلوم نہیں مگر باوجود اس کے سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں.لیکن جنت میں جو سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّ کہا جائے گا وہ علم کی بناء پر ہوگا.وہاں انسان پر کھل جائے گا کہ دنیا میں ہر ایک حقیر سے حقیر چیز یا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ایک سبب اور ایک اثر رکھتا تھا.اور دنیا اور دنیاوالوں کی ترقی یا تنزل یا فائدہ یا نقصان پراثر کر رہا تھا.اور چونکہ اس دنیا کے اعمال اگلے جہان میں مجسم ہوں گے اس لئے اس دنیا کی ہر اک چیز کی حقیقت انسان کو معلوم ہوجائے گی.اور وہ علم کی بناء پر جان لے گا کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی بے حقیقت نہ تھی.بلکہ کوئی حرکت بھی بے حقیقت نہ تھی.پس بے اختیار ہوکر سُبْحَانَکَ اللّٰہُمَّ اس کے منہ سے نکل جائے گا.اور چونکہ دنیا کی تمام تکالیف حقائق اشیاء کے عدم علم کی وجہ سے ہوتی ہیں.حکمت نہ جاننے کی وجہ سے سنکھیا کی مقررہ مقدار سے زیادہ استعمال کرکے لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں.یا مثلاً آگ کھانا پکانے کے لئے بنائی گئی ہے لیکن ایک بچہ اسے اپنے کپڑوں میں لگالیتا ہے اور مر جاتا ہے.غرض تمام بیماریاں اور تکلیفیں چیزوں کی حکمتوں کے نہ جاننے کی وجہ سے آتی ہیں.لیکن جنت میں چونکہ سب حقیقتیں کھل جائیں گی اور حکمتیں معلوم ہوجائیں گی اس لئے حقیقی سلام یعنی کامل سلامتی بھی حاصل ہو جائے گی.کیونکہ حکمتوں کے جان لینے کی وجہ سے وہ چیزوں کی مضرت سے بچ جائیں گے.اور مصیبت اور آفت سے چھوٹ جائیں گے.اس لئے سبحان اللہ کے بعد جو کشف الحقائق ہو جانے پر فوراً ان کے منہ سے علیٰ وجہ البصیرت نکلے گا وہ یہ بھی پکار اٹھیں گے کہ یہاں تو سلامتی ہی سلامتی ہے کیونکہ وہ علم کامل کی وجہ سے چیزوں کے غلط استعمال سے بچ جائیں گے.اور ان کا صحیح استعمال کرکے فائدہ اٹھائیں گے اور جب سلامتی حاصل ہو جائے گی تو بے اختیار الحمدللہ کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام ہمیں عطا فرمایا کہ ہر قسم کے کمالات ہمیں مل گئے اور ہمارے سب اعمال کے سب نتائج اب اچھے ہی اچھے نکلتے ہیں
Page 58
رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ کا لفظ بڑھانے کی وجہ اس جگہ اگر یہ سوال ہو کہ انہوں نے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ کیوں کہا.خالی اَلْحَمْدُلِلہِ کیوں نہ کہہ دیا.حالانکہ یہ کافی تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ رَبُّ الْعٰلَمِیْن ساتھ لگانے کی مختلف وجوہ ہیں.جن میں سے ایک یہ ہے کہ تمام چیزوں کی حکمتوں کو جاننا اور ان سے فائدہ پہنچانا رَبُّ العٰلَمِیْنَ کا ہی کام ہے جو تمام دنیا کی ضروریات کو جانتا ہے.مثلاً ایک گرم ملک میں گرمی کی تکلیف کو دیکھ کر اگر کوئی کہے کہ یہ بڑی مصیبت ہے اور شکایت کرے تو یہ اس لئے ہوگا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس گرمی سے ہی ہزاروں چیزوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے.ان حکمتوں کو رَبُّ الْعٰلَمِیْن ہی سمجھ سکتا ہے.جس کا ہر چیز سے تعلق ہے اور ہر چیز کی حاجتوں کو پورا کرنا جس کا کام ہے.پس اگلے جہان میں جانے پر جب مومنوں کو تمام حقیقتوں اور حکمتوں سے آگاہی ہوجائے گی تو وہ کہیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.بے شک ہم اپنے محدود علم کی وجہ سے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے.کیونکہ رَبُّ الْعٰلَمِیْن خدا ہی ہے جس کی نظر میں سب کچھ ہے باریک در باریک حقیقت سے واقف ہوسکتا ہے سو ہم اس کی حمد کرتے ہیں.وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ۠ بِالْخَيْرِ اور اگر اللہ (تعالیٰ) ان لوگوں پر( ان کے اعمال کی) بدی (کا نتیجہ) ان کے مال کو جلد چاہنے کی طرح جلد وارد کرتا تو لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ١ؕ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ان کی (زندگی کےاختتام کی) میعاد ان پر لائی جاچکی ہوتی (مگر چونکہ ہم نے ایسا پسند نہیں کیا) اس لئے ہم ان لوگوں فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ۰۰۱۲ کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اس حالت میں چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگردان پھر رہے ہیں.حلّ لُغات.اِسْتَعْجَلَ اِسْتَعْجَلَہٗ حَثَّہٗ.اسے کام پر آمادہ کیا.اَمَرَہٗ اَنْ یَّعْجَلَ.اسے جلدی کرنے کے لئے کہا.طَلَبَ عُجْلَتَہٗ وَلَمْ یَصْبِرْ اِلَی وَقْتِہٖ.کسی کام کے لئے کوشش کی کہ وقت سے پہلے ہو جائے.مَرَّفُلَانٌ یَسْتَعْجِلُ اَیْ یُکَلِّفُ نَفْسَہُ الْعُجْلَۃَ.یعنی اپنی طبیعت پر زور ڈال کر تیزی سے چلا.اِسْتَعْجَلَ فُلَانًا سَبَقَہٗ وَتَقَدَّمَہٗ.فلاں شخص سے آگے نکل گیا.(اقرب)
Page 59
خَیْرٌ اَلْخَیْرُ وِجْدَ انُ الشَّیْ ءِ عَلٰی کَمَالَاتِہِ اللَّائِقَۃِ.کسی چیز کا اس کے مناسب حال کمالات کے ساتھ پایا جانا.اَلْمَالُ مُطْلَقًا.خالی مال کو بھی بعض وقت خیر کہہ لیتے ہیں.اَلْخَیْلُ.بہت سے گھوڑوں کو بھی خیر کہہ لیتے ہیں.خیر اس شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں ہر قسم کے کمالات بہ کثرت پائے جائیں.(اقرب) قَضٰی اِلَیْہِ قَضٰی اِلَیْہِ الْاَمْرَ اَنْہَاہُ وَاَبْلَغَہٗ.اس تک اس چیز کو پہنچا دیا (اقرب) اور جب کسی بات کے متعلق ہو تو اس بات کے سنا دینے کے معنی ہوں گے.اور جب کسی چیز کے متعلق ہو تو اس کے معنی اس چیز کے پہنچا دینے کے ہوں گے.پس أَقْضَی اِلَیْہِمْ اَلْاَجَلَ کے معنی ہوں گے ان تک ان کی موت پہنچا دی.یعنی انہیں ہلاک کر دیا.اَجَلٌ اَلْاَجَلُ مُدَّۃُ الشَّیءِ وَوَقْتُہُ الَّذِیْ یَحِلُّ فِیْہِ.اَجَلٌ اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام ہونا ہو.کہتے ہیں ضَرَبْتُ لَہٗ اَجَلًا.میں نے اس کے واسطے فلاں کام کے لئے ایک مدت مقرر کر دی ہے.(اقرب) طُغْیَانٌ طُغْیَانٌمصدر ہے ظَغِیَ یَطْغٰی یا طَغٰی یَطْغِیْ کی اور اس کے علاوہ طغًی اور طِغْیَانًا کی صورت پر بھی اس کی مصدر آتی ہے.طَغٰی کے معنی ہیں جَاوَزَ الْقَدْرَ وَالحَدُّ.اندازہ اور حد سے باہر ہو گیا.طَغَی الْکَافِرُ غَلَا فِی الْکُفْرِ کفر میں زیادہ بڑھ گیا.فُلَانٌ.اَسْرَفَ فِی الْمَعَاصِیْ وَالظُّلْمِ گناہ اور ظلم میں حد سے بڑھ گیا.الْمَاءُ.اِرْتَفَعَ.پانی اونچا ہو گیا.طغیانی اور سیلاب آگیا.(اقرب) عَمِہَ یَعْمَھُوْنَ عَمِہَ سے مضارع کا صیغہ ہے.کہتے ہیں عَمِہَ الرَّجُلُ.جس کے معنی ہیں تَرَدَّدَ فِی الضَّلَالِ وَتَحَیَّرَ فِی مَنَازَعَۃٍ اَوْ طَرِیْقٍ.وہ شخص گمراہی کی حالت میں حیران پھرتا رہا.یا جھگڑے میں یا راستہ میں حیران رہ گیا.کہ اصل حقیقت یا اصل راستہ کون سا ہے.اور یہ بھی محاورہ ہے کہ جب کسی کو دلیل نہ سوجھے یا بات نہ آئے تو اس حالت کو بھی عَمَہٌ کہتے ہیں.جیسا کہ لکھا ہے اَلْعَمَہُ اَنْ لَّا یَعْرِفَ الْحُجَّۃَ.عَمَہٌ کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو دلیل نظر نہ آئے.اس کا اسم فاعل عَامِہٌ ہے اور اس کی جمع عُمّہ اور صیغہ مبالغہ عَمِہٌ ہے.جس کی جمع عَمِہُوْنَ ہے.عَمِہَ اور عَمِیَ میں فرق عَمیَ کا لفظ جو قرآن کریم میں آتا ہے اور جس سے اَعْمٰی کا لفظ بنا ہے اس کے معنی بھی اندھے پن کے ہیں مگر زمخشری کا قول ہے کہ وہ عَمِہَ سے عام ہے.اَعْمٰی اس شخص کو کہتے ہیں جو آنکھ کا یا عقل کا اندھا ہو.مگر عَامِہٌ صرف اس کو کہتے ہیں جو عقل کا اندھا ہو.آنکھ کے اندھے کو عَامِہٌ نہیں کہتے.(اقرب) پس معنی یہ ہوئے کہ اپنی ظالمانہ زیادتیوں میں سرگردان پھرتے ہیں اور پھرتے رہیں گے.اور ان کی عقلیں ماری ہوئی ہیں اور ماری رہیں گی.تفسیر.اِسْتِعْجَالَہُمْ بِالْخَیْرِ کے معنی.اس آیت کے پہلے حصہ کے متعلق بہت اختلاف ہے
Page 60
کہ اس کے کیا معنی ہیں.اور جلدی سے شرپہنچانے اور خیر طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے اِسْتِعْجَالَہُمْ بِالْخَیْرِ کے یہ معنی کئے ہیں کہ جس طرح وہ شر طلب کررہے ہیں اسی طرح اگر ہم بھی جلدی سے انہیں شر پہنچا دیں تو ان کا فیصلہ ہو جائے لیکن یہ معنی عقل کے خلاف ہیں.اگر خیر سے مراد شر ہوتی تو اللہ تعالیٰ شر ہی کا لفظ استعمال نہ فرما دیتا.اصل دقت مطلب کے بیان کرنے میں یہ پیش آتی ہے کہ ان کے خیر کو طلب کرنے پر خدا تعالیٰ انہیں شر پہنچانے کا ذکر کیوں فرماتا ہے.نیکی کے طلب کرنے پر تو انعام ملنا چاہیے تھا.مگر یہ دقت اس لئے پڑی ہے کہ خیر کے سب معنوں پر غور نہیں کیا گیا.اور نہ استعجال کے سب معنوں پر.اگر خیر کے معنی مطلق مال کے لئے جاتے تو یہ دقت نہ ہوتی کیونکہ اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی بنتے کہ جس طرح یہ لوگ دنیوی اموال کے جمع کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اگر اللہ تعالیٰ بھی اس کے بدلہ میں ان کو سزا دیتا چلا جاتا تو ان کا فیصلہ ہو جاتا.مگر خداوند تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا اور توبہ کا موقعہ دیتا ہے.تاکہ جو اصلاح کرنا چاہیں کر لیں اور ان معنوں پر کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا.جو شخص اپنی تمام توجہ دنیا کے اموال کے جمع کرنے پر ہی خرچ کرتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکاتا ہے.اِسْتِعْجَالَہُمْکیضمیر مجرور ہے دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خیر کے معاملہ میں بڑھا ہوا اور آگے نکلا ہوا ہے اگر اسی طرح وہ لوگوں کو عذاب بھی دیتا چلا جاتا تو ان کا فیصلہ ہو جاتا مگر وہ خیر میں تو انسانوں سے آگے نکلا ہوا ہے اور عذاب پہنچانے میں دھیما ہے.ان معنوں کے رو سے ھُمْ کی ضمیر فاعل کی ضمیر نہیں بلکہ مفعول کی ضمیر سمجھی جائے گی برخلاف پہلے معنوں کے کہ ان میں اِسْتِعْجَالَھُمْ میں ھُمْ کی ضمیر فاعلی ضمیر تسلیم کی گئی تھی.اور یہ دونوں باتیں عربی زبان کے لحاظ سے جائز ہیں.اِسْتِعْجَالَھُمْ بِالْخَیْرِ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی.وہ اپنی ساری توجہ دنیا کے اموال کے جمع کرنے میں ہی صرف کررہے ہیں.کیونکہ جب کسی کو کسی کام کے لئے جلدی ہوتی ہے تو وہ دوسرے کام کی طرف مطلقاً توجہ نہیں کرتا.اور اگر کوئی اسے کسی اور کام کی طرف توجہ دلائے بھی تو وہ یہی جواب دے کر چلا جائے گا کہ مجھے جلدی ہے.یہ آیت درحقیقت ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے ہیں تو ہم لوگ عذاب سے جلد کیوں تباہ نہیں کر دیئے جاتے.فرمایا عذاب تو آئے گا مگر اس مہلت کی غرض یہ ہے کہ تا کچھ اور لوگ مان لیں.ترتیب میں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم اکثر اوقات سوال کو حذف کر جاتا ہے اور جواب سے ہی سوال کی
Page 61
طرف اشارہ کر دیتا ہے اس آیت نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ والی آیت میں کفار کے جلد فیصلہ کرنے کا ہی جواب تھا.پس یہ سب آیات بالکل ترتیب کے ساتھ ایک ہی سوال کے جواب کے لئے آئی ہیں.مہلت کیوں دی جارہی ہے فَنَذَرُالَّذِیْنَ سے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم عذاب دینے میں عجلت کرتے تو لازماً لوگ گمراہی پر خاتمہ ہونے کے سبب سے طغیان اور گمراہی میں پڑے رہتے.مگر ہمارا یہ طریق نہیں ہے.ہم تو ہدایت دینا چاہتے ہیں.اس وجہ سے فوراً نہیں پکڑتے تاکہ جس قدر لوگ بچ سکیں بچ جائیں.وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پہلوؤں کے بل( لیٹا ہو ا) یا بیٹھا یا کھڑا ہمیں پکارتاہے.قَآىِٕمًا١ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى پھر جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ( اس طرح سے کترا کر) گذر جاتا ہے( کہ) گویا اس نے ضُرٍّ مَّسَّهٗ١ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ۠ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰۰۱۳ کسی تکلیف (کے دور کرنے) کے لئے جو اسے پہنچی تھی ہمیں نہیں پکارا( تھا).اسی طرح تمام حد سے بڑھ جانے والوں کو جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں خوبصورت کر کے دکھلایا گیا ہے.حلّ لُغات.اِسْرَافٌ.مُسْرِفٌ اَسْرَفَ کا اسم فاعل ہے.کہتے ہیں اَسْرَفَ الْمَالَ.بَذَّرَہٗ.مال کو یونہی بکھیر دیا.ضائع کر دیا.جَاوَزَالْحَدَّ وَأَفْرَطَ فِیْہِ اس کے خرچ میں حد سے بڑھ گیا اور زیادتی سے کام لیا.اور اَسْرَفَ کے معنی أَخْطَأَ کے بھی ہیں یعنی غلطی کی.اور جَہِلَ کے بھی.یعنی اس سے اس طرح علیحدگی کی کہ گویا جانتا ہی نہیں.اور غَفَلَ کے بھی ہوتے ہیں یعنی اس سے غفلت کی.(اقرب) تفسیر.صدمہ رسیدہ کی مختلف حالتیں دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَلْآیَۃ میں صدمہ کی مختلف حالتوں کا ذکر کیا ہے.لِجَنْۢبِهٖۤ کو سجدہ یا شدت خوف سے گر جانے کی حالت کا قائم مقام رکھا ہے.کیونکہ جب انسان کو سخت تکلیف ہو تو اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں.اور وہ گر جاتا ہے.اسی طرح قَاعِدًا اَوْ قَآىِٕمًا ان کی سخت گھبراہٹ اور
Page 62
پریشانی بتانے کے لئے رکھا گیا ہے.کیونکہ ایسے وقت میں انسان کبھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹھ جاتا ہے اور اسے کسی ایک حالت پر قرار نہیں آتا.اور ایک جگہ ٹک نہیں سکتا.یہ ضروری نہیں کہ وہ فی الواقع کھڑا ہو یا بیٹھا ہو.اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ یوں تو زور دیتے رہتے ہیں کہ اگر یہ رسول سچا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا لیکن اگر کبھی عذاب چھو بھی جائے تو سخت گھبرا جاتے ہیں اور سب صبر و قرار جاتا رہتا ہے.آڑے وقت پر دستگیری کرنے والے کی ناشکری مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت بتا کر ہمیں اسلامی اخلاق سکھائے ہیں کہ جب کسی کو مدد کے لئے بلاؤ تو اس سے جدا ہوتے وقت پہلے اس سے اجازت طلب کرو پھر شکریہ ادا کرو.پھر جاؤ.کیونکہ یہ بڑی بدتہذیبی ہے کہ کسی کو مدد کے لئے بلایا جائے مگر اس کا شکریہ بھی ادا نہ کیا جائے.کسی کی نیت پر حملہ کرنا زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ۠ میں اخلاق کے کئی نکتے بیان کئے ہیں.اول یہ کہ کسی کی نیت پر حملہ نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق فرماتا ہے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کرکے دکھائے گئے.ان کو مسرف قرار دے کر بھی ان کی نیت پر حملہ نہیں کرتا بلکہ فرماتا ہے کہ ان کو نظر ہی ایسا آتا ہے.ان کی عقل ہی کمزور ہو گئی ہے.پس کیا ہی تعجب ہے ان مسلمانوں پر جو قلیل سے قلیل اختلاف پر فوراً دوسرے کی نیت پر حملہ کر دیتے ہیں.اس جگہ اگر یہ سوال ہو کہ جب ان کی عقل میں ہی ایسا آتا ہے تو ان کو سزا کس بات کی.تو اس کا جواب یہ ہے کہ سزا کی وجہ بھی انہی الفاظ میں موجود ہے.کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک کو برے اعمال خوبصورت کرکے دکھائے جاتے ہیں.بلکہ یہ فرمایا ہے کہ مسرف کو اس کے برے اعمال خوبصورت کرکے دکھائے جاتے ہیں.پس اسراف کی صفت چونکہ انہوں نے خود پیدا کی تھی اس لئے اس کے نتائج کے بھی وہ خود ذمہ دار ہیں.خواہ وہ نتائج ان کی مرضی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں.اور اس وجہ سے وہ سزا سے بھی بچ نہیں سکتے.نیت ہر جگہ قابل قبول نہیں ہوتی دوسرا نکتہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیت کی دلیل ہر جگہ قابل قبول نہیں ہوتی.بعض دفعہ نیت کی درستی اور شرارت کی عدم موجودگی کے وقت بھی سزا دی جاتی ہے.جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے کہ نیت کو درست تسلیم کرتے ہوئے سزا کا اعلان کیا ہے.یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب نیت اپنے ہی اعمال کی وجہ سے خراب ہو گئی ہو یا یہ کہ نیت کا بدلنا اپنی طاقت میں ہو اور نہ بدلے.جیسے کم علمی اگرچہ ایک عذر ہے لیکن اگر صرف سستی کی وجہ سے ہو تو قابل سزا ہے.ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ کیوں سستی کی.اور علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ طبعی قانون میں تو نیت کا بالکل دخل ہی نہیں ہوتا.خواہ کسی نیت سے کوئی شخص زہر کھائے وہ
Page 63
ضرور ہلاک ہو جائے گا.شریعت میں ایک حد تک لحاظ رکھا جاتا ہے.وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا١ۙ وَ جَآءَتْهُمْ اور یقیناً یقیناً ہم تم سے پہلے قوموں کے بعد قوموں کو جبکہ انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَ مَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا١ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي کھلے نشان لے کر آئے اور (پھر بھی) وہ بالکل ایمان نہ لائے ہم ہلاک کرچکے ہیں الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ۰۰۱۴ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں.حل لغات.قَرْنٌ اَلْقُرُوْنُ الْقَرْنُ کی جمع ہے.اس کے کئی معنی ہیں.کُلُّ اُمَّۃٍ ہَلَکَتْ فَلَمْ یَبْقَ مِنْھُمْ اَحَدٌ ہر ایسی قوم جو تمام کی تمام ہلاک ہوئی اور اس میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا.اَلْوَقْتُ مِنَ الزَّمَانِ زمانہ کے ایک حصہ کو بھی قرن کہتے ہیں.اَھْلُ زَمَانٍ وَّاحِدٍ ایک زمانہ یا ایک نسل کے لوگوں کو بھی قَرْن کہتے ہیں.اُمَّۃٌ بَعْدَ اُمَّۃٍ.زمانہ کے دور کو بھی کہتے ہیں.اور اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے بعد آرہی ہے.عربی کا ایک محاورہ قَرْنُ الشَّیْطَانِ بھی ہے اور اس کے بھی دو معنی ہیں.اَلْمُتَّبِعُوْنَ لِرَأْیِہٖ.شیطانی لوگ.تَسَلُّطُہٗ.شیطان کا تسلط.(اقرب) فَمَا کَانُوْا لِیُؤْمِنُوْا کا جو جملہ اس آیت میں ہے اس کے معنی اردو زبان کے محاوہ کے مطابق یہ ہوں گے کہ انہوں نے ایمان لانے کی طرف توجہ بھی نہ کی.تفسیر.قوموں پر قوموں کی ہلاکت دیکھنے کے باوجود اپنی طاقت پر غرور کرنے کا انجام شروع دنیا سے قوموں کے بعد قومیں ہلاک ہوتی چلی آئی ہیں.ایک مثال نہیں دو نہیں تین نہیں کہ لوگ بھول جائیں.قوموں کے بعد قومیں آئیں اور ہلاک کی گئیں پھر کس قدر نادانی ہے کہ کوئی قوم اپنی ترقی اور ثروت پر نازاں ہو اور اپنی تباہی کی ساعت کو بھول جائے.عذاب الٰہی ظالم پر آتا ہے اس آیت سے بعض الٰہی قانون معلوم ہوتے ہیں.اول یہ کہ عذاب الٰہی ظالم پر آتا ہے.بغیر ظلم کے عذاب نہیں آتا.کیونکہ فرماتا ہے کہ جس قدر قومیں پہلے ہلاک ہوئی ہیں ظالم ہو جانے کے سبب
Page 64
سے یعنی دینی یا دنیاوی احکام کو نظرانداز کر دینے کے سبب سے ہلاک ہوئی ہیں.دوسرے یہ کہ باوجود ظالم ہونے کے بھی کوئی قرن ہلاک نہیں ہوتی جب تک اس کے پاس رسول نہ آجائیں.اور اسے اس کی غلطیوں پر متنبہ نہ کر دیں.کیونکہ فرمایا کہ سب قوموں کو ہم نے اسی وقت ہلاک کیا جب کہ ظالم ہوجانے کے بعد ان کے پاس رسول بھی آگئے.اور انہوں نے ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا.عذاب کا آنا نبی کے آچکنے کی دلیل ہے كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ.یعنی جب تک کوئی قوم ظلم نہ کرے اور پھر اسے نبی بھیج کر متنبہ نہ کر دیا جائے اس وقت تک ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا کرتے.پس اس جگہ بھی رحم پر زور دینا مقصود ہے نہ کہ عذاب پر.کیونکہ فرمایا ہم تو کسی قوم کو بدیوں میں مبتلا دیکھ کر ان پر اپنا رحم نبی کی صورت میں نازل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بدکرداریوں کے بد نتائج سے محفوظ ہوکر اس نبی کی اتباع کرکے ہمارے انعامات کے وارث ہوں لیکن وہ اس کی مخالفت کے خطرناک جرم کے مرتکب ہو کر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں.تعجب آتا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ اپنے منہ سے عذاب کا اقرار کرتے ہیں مگر نبی کے آنے کو تسلیم نہیں کرتے.عذاب کی دو قسمیں عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) طبعی (۲) شرعی.شرعی عذاب کے لئے یہ شرطیں ہیں.کہ لوگ ظلم کریں.اور نبی مبعوث ہو تب عذاب آوے.مگر طبعی عذاب کے لئے یہ شرط نہیں بلکہ جو قوم دنیوی طور پر کمزور اور ترقی کے اسباب سے غافل ہوگی اس کو ہلاک کر دیا جائے گا.ان کی ہلاکت کا موجب ان کی دنیوی کمزوری ہو گی نہ کہ خدا کی محبت کی کمی.شرعی عذاب کی علامات شرعی عذاب کی پہچان اس طرح ہوجاتی ہے کہ اس کے اندر بعض غیر معمولی باتیں پائی جائیں.مثلاً عذاب کی صورت اور اس کا رنگ ڈھنگ ایسا ہو جو عام طور سے کبھی طبعی عذاب کی صورت میں نہ پایا جائے.مثلاً اس کے متعلق پہلے سے پیشگوئیوں کے ذریعہ سے خبر دی جائے.یا غیر معمولی طور پر قانون قدرت میں انقلاب پیدا ہو مثلاً یک دفعہ زلزلے پر زلزلے شروع ہو جائیں.بیماریاں قحط اور دوسری قسم کے مصائب ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں.ان صورتوں میں ماننا پڑے گا کہ وہ تغیرات جو دنیا میں ہورہے ہیں شرعی عذاب ہیں اور ضرور کوئی رسول مبعوث ہوا ہے.ان شرعی عذابوں کے علاوہ طبعی عذاب ہمیشہ دنیا پر آتے رہتے ہیں.پس ان لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں قوم تباہ ہوئی.ان کی بادشاہت جاتی رہی.اس وقت ان میں کون سا نبی آیا تھا؟ حالانکہ قوموں کی تباہی اور بادشاہوں کی بربادی ایک طبعی امر ہے.ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ پہلے تم یہ ثابت
Page 65
کرو کہ یہ عذاب غیرطبعی تھا.اور پھر بتاؤ کہ اس وقت کوئی نبی نہ تھا.مگر یہ بات وہ ہرگز ثابت نہیں کرسکتے.یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عذاب کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ قرن پر آئے.یعنی ایک پوری امت پر نازل ہو.نہ کہ بعض حصۂ قوم پر.افراد یا مجموعہ افراد پر تو ہر زمانہ میں عذاب آتا رہتا ہے.حتیٰ کہ نبی کے زمانہ میں بھی اس کی جماعت کے بعض افراد پر عذاب آتا رہتا ہے.ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓىِٕفَ فِي الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں( ان کا) جانشین بنایا كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ۰۰۱۵ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو.حلّ لُغات.خَلِیْفَۃٌ خَلَائِفُ اور خُلَفَاءُ لفظ خَلِیْفَۃٌ کی جمع ہے.اس کے معنی ہیں مَنْ یَّخْلُفُ غَیْرَہٗ وَیَقُوْمُ مَقَامَہٗ.جو کسی کے پیچھے آئے اور اس کی جگہ لے.اَلسُّلْطَانُ الْاَعْظَمُ وَ فِی الشَّرْعِ الْإِمَامُ الَّذِیْ لَیْسَ فَوْقَہٗ اِمَامٌ.(اقرب) ’’وہ پیشرو اور حاکم جس کے اوپر اور کوئی حاکم اور پیشرو نہ ہو‘‘.تفسیر.لِنَنْظُرَ پر ایک سوال یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو قائم مقام بناتے وقت ہی دیکھ لئے گئے تھے کیونکہ ہر قوم جو دوسری قوم کے بعد آئے گی اور اس کی خلیفہ بنائی جائے گی وہ لازماً پہلوں کی نسبت اچھی ہو گی.تبھی تو وہ خلیفہ بنائی گئی.اور پہلی کو تباہ کیا گیا.یہ تو ہوسکتا ہے کہ قائم مقام قوم بعض اور باتوں میں پہلی سے ادنیٰ ہو مثلاً پہلی قوم فن معماری میں کمال رکھتی ہو بعد میں آنے والی قوم ویسی نہ ہو.مگر یہ نہیں ہوسکتا کہ جس امر میں اسے قائم مقام بنایا گیا ہے اس میں وہ پہلی سے کمزور ہو.پس جب ایک قوم کو قائم مقام بنایا ہی اس لئے گیا تھا کہ وہ عمل میں پہلی سے اچھی تھی تو اس کا مطلب کیا ہوا.کہ ہم اس لئے جانشین بناتے ہیں کہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو.اعمال کی دو قسمیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عمل دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک وہ عمل جو انسان کو نعمت کا مستحق بناتے ہیں.اور دوسرے وہ عمل جو نعمت کے ملنے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لئے کرنے ضروری ہوتے ہیں.کئی طالبعلم طالبعلمی میں ہوشیار ہوتے ہیں مگر جب زندگی کی کشمکشوں میں پڑتے ہیں تو بالکل نکمے ثابت ہوتے ہیں.یہی قوموں کا حال ہوتا ہے.بعض قومیں شان و شوکت کے ملنے سے پہلے بہت اچھا نمونہ دکھاتی ہیں مگر جب حکومت
Page 66
مل جاتی ہے تو نیکی کے معیار کو قائم رکھنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے.دوسرے اس جملہ کو اس لئے بھی بڑھایا گیا ہے کہ انسانی اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک خود عمل صالح اور ایک وہ عمل جو عمل صالح کو قائم رکھے.پس اس جملہ کے بڑھانے سے یہ بھی مطلب ہے کہ تمہاری ذاتی نیکیوں کی وجہ سے ہم نے تم کو خُلَفَآء فِي الْاَرْضِ بنایا تھا.اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ان اعمال کو کس طرح بجالاتے ہو.جو نیکی کے محافظ ہوتے ہیں حق یہی ہے کہ نیک اعمال سے بہت زیادہ مشکل وہ اعمال ہوتے ہیں جو نیکی کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں.قوموں کی تباہی کا باعث ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ترقی کے لئے تو کوشش کرتی ہیں مگر اس کو قائم رکھنے کے لئے کوشش نہیں کرتیں.اپنے تقویٰ کا خیال رکھتی ہیں مگر اولاد کے اخلاق کی طرف پوری توجہ نہیں کرتیں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا نیکی کا معیار گرنے لگتا ہے.حتیٰ کہ آخر میں لفظ رہ جاتے ہیں اور حقیقت مفقود ہوجاتی ہے.اور چونکہ یہ تغیر کئی نسلوں میں ہوتا ہے اس کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا.اور آخر قوم تباہی کے گڑھے میں گر جاتی ہے.پس اس جملہ میں اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تم اپنی خلافت کو کتنی دیر تک قائم رکھتے ہو.مسلمانوں کا اپنی اولاد کی تربیت سے تغافل اگر مسلمان اس بے مثل نکتہ کا خیال رکھتے تو آج ان کا یہ حال نہ ہوتا.انہوں نے ایک وقت اپنی اولادوں کی تربیت کے فرض سے کوتاہی کی اور ان کی ناجائز محبت ان پر غالب آگئی یا انہوں نے شادیوں میں احتیاط سے کام نہ لیا اور ایسی عورتوں کو اپنے گھروں میں لائے جو اسلامی تربیت کی قابلیت نہیں رکھتی تھیں اور وہ عظیم الشان عمارت جو صحابہ ء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تیار ہوئی تھی اپنی بنیادوں پر گر گئی.اِنَّالِلہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ.اگر آگے ہی کو وہ قوم جسے خدا تعالیٰ نے اسلام کی ترقی کے لئے چنا ہے اس امر کا خیال رکھے تو انشاء اللہ دنیا میں ایک زبردست تغیر پیدا ہوسکتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فرض کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِیَّتِہٖ.تم میں سے ہر ایک شخص علاوہ اپنی ذات کی ذمہ داری کے بعض دوسرے وجودوں کا بھی ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے صرف یہی نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا عمل کئے بلکہ یہ بھی پوچھے گا کہ جن کی ذمہ داری تمہارے سر پر تھی انہیں تم نے کس قابل بنایا؟ پس خالی اپنے نفس کی طہارت انسان کے کام نہیں آسکتی.
Page 67
وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ١ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہہ دیتے ہیںکہ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَاۤ اَوْ بَدِّلْهُ١ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْۤ (اے محمد) تو اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آیااس میں (ہی کچھ) تغیر( و تبدل) کر دے.تو (انہیں) کہہ (کہ یہ) میرا اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ١ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى کام نہیںکہ میںاس میں اپنی طرف سے( کوئی) تغیر( و تبدل) کردوں.میں (تو) جو (کچھ) مجھ پر وحی (سے حکم نازل ) اِلَيَّ١ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ۰۰۱۶ کیا جاتا ہے (فقط) اسی کی پیروی کرتا ہوں.اوراگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو (اس صورت میں) میں ایک بڑے (ہولناک) دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں.حلّ لُغات.تَلَا تَلَا الْکَلَامَ تِلَاوَۃً قَرَءَ ہٗ.یعنی کسی اور کا کلام یا اپنا لکھا ہوا کلام یاد سے یا تحریر سے پڑھ کر سنایا.(اقرب) ان الفاظ کا ترجمہ ’’ان پر پڑھی جاتی ہیں‘‘ کرنا اردو محاورہ کے خلاف ہے اور پڑھنے والا اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکتا.لَایَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَا کے معنی کے لئے دیکھو.یونس آیت نمبر۸.مَایَکُوْنُ لِیْ.میرے لئے کیسے ممکن ہوسکتا ہے.تِلْقَاءَ اَلتِّلْقَآءُاِسْمٌ مِّنَ اللِّقَاءِ وَیُتَوَسَّعُ فِیْہِ فَیُسْتَعْمَلُ ظَرْفًا لِمَکَانِ اللِّقَاءِ وَالْمُقَابَلَۃِ فَیُنْصَبُ عَلَی الظَّرْفِیَّۃِ یُقَالُ تَوَجَّہَ تِلْقَآءَ النَّارِ وَجَلَسَ تِلْقَآءَ فُلَانٍ اَیْ حَذَاءَ ہٗ (اقرب) یعنی تِلْقَاءَ لِقَاء کا اسم ہے لیکن اس کے معنوں کو وسیع بھی کر لیا جاتا اور اسے مقابل کی جگہ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے.اس وقت اسے ظرف قرار دے کر نصب دیتے ہیں.کہتے ہیں تَوَجَّہَ تِلْقَاءَ النَّارِ اس نے آگ کی طرف منہ کیا.یا جَلَسَ تِلْقَاءَ فُلَانٍ.فلاں شخص کے سامنے بیٹھا.جب یہ لفظ نفس کی طرف مضاف ہو تو عِنْد کے معنوں میں آتا ہے کہتے ہیں.مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِیْ اَیْ مِنْ عِنْدِ نَفْسِیْ.یعنی اپنی مرضی سے کام کیا.کسی کے مجبور کرنے سے نہیں کیا.(اقرب)
Page 68
تفسیر.اس آیت میں بینات کا لفظ آیات کا حال مؤکد ہے.جس کا ترجمہ نعت کی طرح کیا جاتا ہے اور اکثر مقامات پر انبیاء کے ذریعہ سے جو نشانات یا کلام دنیا کو سنایا جاتا ہے اس کے لئے بینات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ آیات دو قسم کی ہوتی ہیں.ایک محض آیات.دوسری آیات بینات.بعض آیات غیر بین بھی ہوتی ہیں دنیا کا ہر ذرہ ایک آیت ہے.کیونکہ عقلاً وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا موجود ہے.لیکن ہم یہ امر اپنے قیاس سے معلوم کرتے ہیں.وہ دلیل خود اس امر کی طرف اشارہ نہیں کرتی.کہ میں اس غرض سے پیدا کی گئی ہوں.مگر وہ آیات جو انبیاء کی معرفت آتی ہیں ان کے ساتھ یہ امر بھی واضح کر دیا جاتا ہے کہ وہ امور غیبیہ پر بطور دلالت کے نازل کی گئی ہیں.اور اصل مقصود ان سے ہستی باری کا ثبوت ، نبیوں کی شہادت، صفات الٰہیہ کے ظہور کی حقیقت ،بعث مابعد الموت کا انکشاف ہے.پس چونکہ ان آیات کے متعلق صاف کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایمانی امور کے لئے بطور گواہ کے ہیں.ان کا نام برخلاف قانون قدرت کی آیات کے آیات بینات رکھا جاتا ہے.مثلاً وبائیں ایک آیت ہیں.لیکن وہ وباء جس کی نبی پہلے سے خبر دیتا ہے اور لوگوں کو ہوشیار کر دیتا ہے کہ وہ میری صداقت کے ثبوت کے طور پر ظاہر ہو گی.آیت ہی نہیں بلکہ آیۂ بینہ ہے.کہ عام وباء کی نسبت زیادہ وضاحت سے اپنے مقصد کو ظاہر کررہی ہے.قرآن کریم کے بدلنے کا مطالبہ منکر لوگ ان آیات بینات کو سن کر بجائے فائدہ اٹھانے کے دو مطالبے کرتے ہیں.ایک یہ کہ اس قرآن کی بجائے اور قرآن لے آؤ.دوسرا یہ کہ اگر یہ نہ کر سکو تو کم سے کم اس میں تبدیلی کر دو.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مطالبات ان کے دل کی سختی اور زنگ آلودگی کے سبب سے ہیں.کیونکہ ان کے پاس نشانات تو آ چکے ہیں مگر باوجود ان نشانات کے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا.پس معلوم ہوا کہ ان کا مقصد فائدہ اٹھانا نہیں ہے بلکہ بوجہ اس کے کہ دل ایمان سے خالی ہیں ہنسی اور شرارت مقصود ہے اور چاہتے ہیں کہ نشانات کا جو اثر پبلک پر پڑا ہے اس کو دور کر دیں.اس مطالبہ کی غرض لوگوں کو نبی کے خلاف بھڑکانا ہے اَلَّذِیْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا کے جملہ سے صاف ثابت ہے کہ نشانات کو دیکھ کر عوام میں سے بعض کے دل نرم ہو گئے ہیں.ان کی اس حالت کو دیکھ کر ائمۃ الکفر کو فکر پڑتی ہے اور وہ ایسی چال چلنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات پھر مخالفت میں ابھر پڑیں.اور آخر مصلح کی شکل اختیار کرتے ہیں.انسانی فطرت صلح کے طریق کو پسند کرتی ہے.اور صلح کے مطالبہ پر امور متنازعہ فیہا کی اہمیت کو بسا اوقات نظرانداز کر کے صرف اس امر کو اپنے ذہن میں جما لیتی ہے کہ خواہ کچھ قربانی کرنی پڑے صلح کرلینی
Page 69
چاہیے.وہ لوگ بھی یہی چال چلتے ہیں.اور درمیانی راہ پر آجانے کی دعوت دیتے ہیں.اور اول تو مطالبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یعنی تم بڑے کام کرنے والے ہو اپنی نئی تعلیم پیش نہ کرو.قوم کے لیڈر بن کر اسی کے خیالات کے مطابق کام کرو.تو ہم سب لوگ تمہارے پیچھے چلنے کو تیار ہیں.اس طرح ملک کا فساد دور ہو جائے گا.اور بھائی سے بھائی جدا نہ ہوگا.اور اگر تم ایسا پسند نہیں کرتے تو دوسری تجویز ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ کم سے کم ایسے مضامین کو بیچ میں سے اڑا دو جن سے تمہاری قوم کو رنج ہوتا ہے.مثلاً شرک کے خلاف تعلیم یا قومی رسوم کے خلاف تعلیم.اس تجویز کے پیش کرتے وقت آئمۃ الکفر خوب جانتے ہیں کہ آپ ان امور کو تو مان نہیں سکتے پس لوگوں کے جذبات پھر بھڑک اٹھیں گے کہ یہ کس قدر تنگ خیال آدمی ہے.کہ قوم اور ملک میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے اپنے بعض خیالات چھوڑنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا.اور یہ بھول جائیں گے کہ بے شک قوم اور ملک ایک اہم چیز ہیں لیکن سچائی ان سے بھی اہم ہے.اور یہ بھی خیال نہ کریں گے کہ قوم کا تنزل تو ان سچائیوں کے انکار کی وجہ سے ہے پس وہ صلح کس فائدہ کی.جس میں ان سچائیوں کو چھپایا جائے جن پر قومی ترقی کا انحصار ہے.اور اس طرح قوم کو ہمیشہ کے لئے کامیابی کے راستہ سے پھرا دیا جائے.آہ یہ خیال ہمیشہ تنزل کی طرف جانے والی اقوام میں راسخ ہوتا ہے کہ انہیں ان کے موجودہ نظام کو بدلے بغیر ترقی نصیب ہو جائے.اور وہ ہمیشہ مصلحین کے خلاف یہی رویہ اختیار کرتی ہیں کہ قومی صلح کو باقی سب امور پر ترجیح دیتی ہیں.حالانکہ اس سے زیادہ جھوٹ اور کوئی نہیں ہوتا کہ ایک گری ہوئی قوم میں حقیقی صلح ہو.قرآن کریم فرماتا ہے قُلُوْبُهُمْ شَتّٰى.ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں اس کے باوجود وہ سب فساد کا الزام اپنے وقت کے مصلحوں پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے فساد ڈال دیا.اور قومی صلح کے نام سے صداقتوں کی قربانی میں اخفاء کا مطالبہ کرتے ہیں.جسے کوئی راست باز انسان قبول نہیں کرسکتا.اور اس سے دشمنانِ حق کو اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا موقع مل جاتا ہے.بالکل اسی طرح آج کل مسلمانوں میں ہو رہا ہے.مگر افسوس کہ باوجود قرآن کریم میں اس حقیقت کے واضح کر دینے کے وہ اپنی حالت کو سمجھتے نہیں.اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے.اس مطالبہ کا جواب اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ا ئمۃ الکفر کی اس تدبیر کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو ان سے کہہ دے کہ میں اپنی طرف سے اس تعلیم کو کیسے بدل سکتا ہوں.تم جانتے ہو کہ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں اپنی عقل سے اس تعلیم کو پیش کرتا ہوں.اگر میری عقل کا سوال ہوتا تو بے شک کہا جاسکتا کہ ایک فرد کی عقل کو قوم کی عقل کے تابع کر دیا جائے مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ نسخہ ہے.اس میں تبدیلی نسخہ کی غلطی کی وجہ سے تو ہو نہیں سکتی
Page 70
ہاں صرف اس طرح ہوسکتی ہے کہ تم لوگ اپنی حالتوں کو بدل لو.اس فقرہ میں اس بات کی طرف بھی ایک لطیف اشارہ فرمایا ہے کہ الٰہی تعلیم انسانی حالت کے مطابق ہوتی ہے.اور وہی اصلاح اور علاج کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے.اس لئے فرمایا کہ اگر میں اسے اپنے پاس سے بدل دوں تو اس بات کا بہت بڑا نقصان ہو گا کیونکہ صرف یہی تعلیم تمہاری اصلاح کرسکتی ہے.پس اس میں تبدیلی کرنا یقیناً اصلاح نہیں ہوگا بلکہ تکلیف دہ ہوگا.دوسرے اس سے یہ بھی مرا دہوسکتی ہے کہ اس میں جو تمہاری تباہی، بربادی اور عذاب کی خبریں دی جاتی ہیں اور تم انہیں ناپسند کرتے ہو اور انہیں بدلنے کے لئے کہتے ہو جب تم میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی تو یہ تمام خبریں خود بخود بدل جائیں گی.اور اس وقت تم کو ترقی، کامیابی اور غلبہ کی بشارات کا وارث بنا دیا جائے گا.گویا یہ خبریں تب ہی بدلیں گی جب تمہاری حالت بدلے گی.میرا کام نہیں کہ ان کو خود بدلوں.کیا نبی وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں اپنے پاس سے نہیں بدل سکتا.جب تک خدا نہ بدلے.کیونکہ میں تو صرف وحی الٰہی کی پیروی کرنے والا ہوں.یہاں یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ کیا نبی وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر وحی کے کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا.جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بغیر وحی کے کوئی کام نہیں کرتا تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ محبت الٰہی میں اس قدر گداز ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے وحی الٰہی سے ہی بعض کاموں میں عقل سے کام لینے کا حکم نہ دے تو وہ کچھ بھی بغیر وحی کے نہ کرے.لیکن چونکہ وحی الٰہی ہی اسے کہتی ہے کہ وہ استنباط اور استخراج کے طریقے کو جاری رکھے اس لئے وہ عقل سے بھی کام لیتا ہے.اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی استنباط سے کام نہیں لیتا صرف وحی کا ہی تابع ہوتا ہے اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت استنباط بھی کرتا ہے اس لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ استنباط سے بھی کام لیتا ہے لیکن یہ ہرگز درست نہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ نبی جو کچھ کہتا یا کرتا ہے صرف وحی سے کہتا اور کرتا ہے.کیونکہ اس طرح ان اجتہادی غلطیوں کا جو انبیاء سے ہوتی رہتی ہیں کوئی جواب نہ ہوگا.اور نبی کو نعوذباللہ من ذلک خدا تعالیٰ کی وحی کے خلاف عمل کرنے والا سمجھنا پڑے گا.جیسے مثلاً یہ آیت عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ١ۚ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ (التوبۃ:۴۳) اللہ تعالیٰ تجھ پر فضل کرے تو نے کیوں (تبوک کے غزوہ میں جانے سے اجازت مانگنے والوں کو) اجازت دی جب تک کہ تجھ پر سچوں کی حقیقت نہ ظاہر ہوجاتی اور جھوٹوں کا جھوٹ نہ کھل جاتا.اب اگر یہ سمجھا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اک کام خدا تعالیٰ کی وحی سے کرتے تھے تو نعوذباللہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس موقع پر آپ نے وحی الٰہی کے خلاف کام کیا.
Page 71
قرآن کریم کے جمع وغیرہ کاتمام کام بھی وحی الٰہی کے ماتحت ہی ہوا ہے ہاں! اس آیت کے ایک اور معنی بھی ہوسکتے ہیں اور وہ یہ کہ اس جگہ قرآن مجید کا ذکر ہے اور انہوں نے ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَاۤ ہی کہا ہے اس لئے اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَیَّ بھی قرآن مجیدسے ہی متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے متعلق تمام باتیں وحی الٰہی سے کرتا ہوں اور اس میں خود کوئی دخل نہیں دیتا.لہٰذا میں کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کرسکتا.اس آیت سے ان لوگوں کا رد بھی ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ہر سورۃ سے پہلے لکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے نہ کہ وحی سے.یا ترتیب قرآن اور سورتوں کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے فرماتا ہے کہ قرآن مجید کے متعلق میں ہر بات کو وحی سے ہی طے کرتا ہوں اور یہ کہنا کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی الٰہی سے ایسا کرتے تھے مگر صحابہ نے اپنی مرضی سے بعض تغیرات کر دیئے بالکل ہی عقل کے خلاف ہے.کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں تھا تو صحابہ کو کیسے یہ حق حاصل ہو سکتا تھا.اور وہ سوائے اس کے کہ نعوذباللہ انہیں مرتد قرار دیا جائے کب ایسا کرسکتے تھے.قرآن کریم کا کوئی حصہ یا کوئی آیت منسوخ نہیں اس آیت پر بعض مسیحی مصنف اعتراض کرتے ہیں کہ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰۤى اِلَيَّ اور مَا يَكُوْنُ لِيْۤ اَنْ اُبَدِّلَهٗ میں نسخ قرآن کے مسئلہ پر جو اعتراض پڑتا تھا اس سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے.اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کا مجھ پر الزام نہیں آسکتا.یہ تو جو کچھ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے.لیکن یہ خیال بالکل فضول ہے کیونکہ اس جگہ پر نسخ کا جواز نہیں نکلتا.بلکہ یہ آیت تو بتاتی ہے کہ نسخ قرآن مجید میں کبھی ہوا ہی نہیں کیونکہ کفار جو بَدِّلْہٗ کا مطالبہ کرتے تھے ان کی غرض اس سے یہ تو نہ تھی کہ وہ تبدیلی کے بعد مان لیں گے.بلکہ ان کی صرف یہ غرض تھی کہ بعد میں اعتراض کریں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے جبھی تو حسب منشاء تبدیلی کرلیتے ہیں اور اگر نہ بدلیں گے تو قوم کو اکسائیں گے کہ یہ شخص قوم کی صلح اور اتحاد کو پسند نہیں کرتا.لیکن اگر پہلے ہی قرآن کریم میں نسخ ہوا کرتا تھا تو انہیں اس مکارانہ تدبیر کے اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ پہلے نسخ جو قرآن کریم میں ہو چکے تھے ان پر اعتراض کر دیتے.پس یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید میں نسخ بالکل نہیں ہوا.کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ فلاں آیت کی جگہ فلاں آیت رکھی گئی ہے یہ عجیب بات ہے کہ وضاعوں نے ایسی روایات تو بنالیں کہ فلاں آیت اب نہیں ملتی یا فلاں سورۃ کا پتہ نہیں چلتا لیکن ایسی روایات بنانے کی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں گیا کہ قرآن مجید کی فلاں آیت منسوخ ہو گئی اور اس کی جگہ فلاں آیت رکھی گئی ہے.
Page 72
قرآن کریم میں کوئی تبدیلی یا نسخ ہونا غرض نزول قرآن کریم کے منافی ہے اِنِّيْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ کے یہ معنی نہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ عذاب عظیم پہنچے گا تو میں تبدیلی یا تغیر کر دیتا کیونکہ آیت کے یہ الفاظ نہیں کہ مجھ پر عذاب نازل ہوگا.اس سے میں ڈرتا ہوں.بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو یوم عظیم کا عذاب آجائے گا.اور یوم عظیم کا عذاب قومی عذاب ہوتا ہے کیونکہ وہ وسیع ہوتا ہے اور دنیا پر ایک مستقل اثر چھوڑ جاتا ہے.پس اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم آتی ہے وہ خود لوگوں کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے.اور تمام ترقی اس سے وابستہ ہوتی ہے.پس اگر اس تعلیم میں تبدیلی کر دی جائے تو اس کا نقصان خود ملک اور قوم کو پہنچے گا اور قوم کی تباہی کا دن آجائے گا.پس اس کے بدلنے میں قوم کی خیرخواہی نہیں ہے.بلکہ اس کے قائم کرنے میں قوم اور ملک کی خیرخواہی ہے.یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی بیمار ڈاکٹر سے کہے کہ اس نسخہ کی فلاں دوائی بدل دو تب میں کھاؤں گا تو ڈاکٹر کہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ نسخہ بدلنے سے تکلیف ہوگی.تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو بدل دیتا بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نسخہ یہی مفید ہے.قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ١ۖٞ (اور) تو (انہیں) کہہ کہ اگر اللہ( تعالیٰ) کی( یہی) مشیت ہوتی (کہ اس کی جگہ کوئی اور تعلیم دی جائے) تو میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ١ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۰۰۱۷ اسے پڑھ کر تمہیں نہ سناتا اور نہ وہ( ہی) تمہیں اس( تعلیم )سے آگاہ کرتا.چنانچہ اس سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں گذار چکا ہوں.کیا پھر (بھی) تم عقل سے کام نہیں لیتے.حلّ لُغات.دَرٰی درٰی یَدْرِیْ دَرْیًا وَدِرَایَۃً عَلِمَہٗ.دَرٰی کے معنی ہوتے ہیں.اسے جان لیا (اقرب) اَدْرٰی بِہٖ اَعْلَمْہٗ بِہٖ.اسے اس کا علم دیا.(اقرب) لَبِثَ لبِثَ بِالْمَکَانِ یَلْبَثُ لَبْثًا وَلُبْثًا وَلِبَاثًا.مَکَثَ وَ اَقَامَ.مکان میں رہا یا ٹھہرا.قَدْ قَدْکا لفظ جب ماضی پر آئے تو اس کے معنی کو حال کے قریب کر دیتا ہے.پس اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ میں تم میں نبوت کے زمانہ تک رہتا چلا آیا ہوں کہیں غائب نہیں ہوا.
Page 73
تفسیر.بطلان عقیدہ نسخ فی القرآن یعنی جیسا کہ تم اس کے بدلنے کے لئے کہتے ہو اگر اس کا بدلنا مفید ہوتا اور دوسرا نسخہ کام آسکتا تو وہ نسخہ پہلے ہی کیوں نہ آجاتا.اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس آیت سے نسخ کے عقیدہ پر سخت حملہ ہوتا ہے.نسخ صرف احکام میں ہوسکتا ہے.وہ بھی صرف اس لئے کہ بعض اوقات ایک حکم مفید ہوتا ہے.بعض اوقات دوسرا.لیکن اگر حالات کے بدلنے کے بغیر نسخ ہو جائے تو ماننا پڑے گا کہ وہ پہلی تعلیم اپنی ذات میں مفید نہ تھی.اور اس کا پیش کرنا ہی غلط تھا.اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے کہ تو ان سے کہہ دے کہ اگریہ تعلیم مفید نہ ہوتی بلکہ کوئی اور تعلیم تمہاری حالت کی اصلاح کرسکتی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم پاکر میں اس تعلیم کو کیوں تمہیں سناتا اور خدا تعالیٰ کیوں یہ تعلیم بھیجتا؟ دعوی نبوت سے قبل کی زندگی ایک بہت بڑا معیار صداقت ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ.میں ایک بہت بڑا اصل مدعی نبوت کی صداقت کے پہچاننے کا بیان کیا گیا ہے.بلکہ ہر شخص کے حالات کی پرکھ اس اصل پر ہوسکتی ہے.بشرطیکہ اس کے معنوں کو ناجائز وسعت نہ دے دی جائے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ نبوت یا قرآن کریم کے نزول کے زمانہ سے پہلے زمانہ کو بطور شہادت کفار کے سامنے پیش کریں کہ اس میں میری زندگی صداقت کا ایک اعلیٰ نمونہ رہی ہے.اور اس زمانہ اور نبوت کے زمانہ میں کوئی وقفہ نہیں پڑا.میں تمہاری نظروں سے غائب نہیں رہا.کہ تم خیال کرو کہ اس عرصہ میں میں بگڑ گیا ہوں گا.جب تم تسلیم کرتے ہو کہ عمر بھر میں پکا راستباز رہا ہوں اور امین کہلاتا رہا ہوں تو ان اعمال کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے انعام ملنا چاہیے تھا نہ یہ کہ میں یکدم ایک ہی رات میں جھوٹا اور فریبی ہو جاتا.کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص کل شام تک سب سے بڑا سچا ہو صبح ہوتے تک دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہو جائے.کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ جھوٹا اور کوئی نہیں ہوسکتا.جو شخص بندوں پر جھوٹ نہیں باندھتا وہ خدا تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ انتہائی تغیر یکلخت نہیں ہوا کرتا انسانی فطرت کا قاعدہ ہے کہ اس میں انتہائی تغیر خواہ نیکی کی طرف ہو یا بدی کی طرف یک لخت نہیں ہوتا بلکہ ایسے تغیر کے لئے ایک عرصہ چاہیے.لیکن آیت کے الفاظ بتارہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے اور آپ کی تمام عمر آپ کے ہم وطنوں کے لئے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی.پس اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو مخاطب کرکے فرماتا ہے کہ تم ہمارے رسول کی طرف جھوٹ تو وہ منسوب کرتے ہو جو سب سے بڑا جھوٹ ہے.یعنی خدا پر افترا کرنا.لیکن اس کے نشوونما کے لئے کسی عرصہ کا ثبوت نہیں دے سکتے بلکہ اس کے برخلاف تم خود تسلیم کرتے ہو کہ یہ رسول دعویٰ نبوت کی گھڑی
Page 74
تک تمہارے درمیان رہتا رہا ہے اور اس گھڑی تک تم اس کو نیک پاک امین اور راستباز ہی قرار دیتے رہے ہو.پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص اپنے پاس سے جھوٹ بنا کر تم کو یہ تعلیم دے رہا ہے؟ دعویٰ کے بعد کےاعتراضات قابل التفات نہیں مِنْ قَبْلِهٖ کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ دعوائے نبوت کے بعد کے اعتراض قابل التفات نہیں.کیونکہ اس وقت مخالفت کے باعث دشمنی پیدا ہوجاتی ہے.اس نکتہ کو ہرقل بادشاہ روم نے بھی خوب سمجھا تھا.کیونکہ جب اس نے ابوسفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن کے متعلق شہادت طلب کی تو اس سے یہی مطالبہ کیا تھا کہ آپ کا چال چلن اس دعویٰ سے پہلے تمہارے نزدیک کیسا تھا.فوری تغیر کے اسباب اَفَلَا تَعْقِلُوْنَکہہ کر بتایا ہے کہ اس کے خلاف بات کہنا عقل کے خلاف ہے کیونکہ یہ بات علم النفس سے ثابت ہے کہ فوری تغیر دو اسباب کے بغیر نہیں ہوتے یا تو جسمانی تغیر کے سبب سے جیسے کہ کسی انسان کے دماغ کو چوٹ وغیرہ کے ذریعہ سے کوئی صدمہ پہنچ جائے جس سے اس کا حافظہ جاتا رہے.یا اخلاق بگڑ جائیں.یا اخلاق کی اصلاح ہو جائے.یا پھر کسی عظیم الشان روحانی تغیر سے یکدم تغیر ہوتا ہے.جیسا کہ مثلاً بعض دفعہ کسی انسان کو کوئی عظیم الشان صدمہ پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے مایوسی کا پہلو اختیار کرکے بدی کی طرف جھک جاتا ہے.یا کسی عظیم الشان صداقت کا انکشاف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یک دم نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے.ان دو تغیرات کے بغیر انسان میں فوری تغیر نہیں ہوتا.بلکہ تدریجی تغیرات ہوتے ہیں.لیکن تاریخ سے ہرگز ثابت نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو.نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر.کیونکہ نبوت سے ایک عرصہ پہلے آپ دنیا کو ترک کرکے علیحدہ عبادت کرنے کے عادی تھے.اور اپنے اہل وطن سے مایوس نہ تھے.بلکہ ان کے ہم درد اور خیر خواہ تھے.اور ان کی ترقی کے لئے کوشش کرتے تھے.پس ان حالات میں بالکل خلاف عقل ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ کل تک تو بے شک یہ شخص نیکی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا مگر آج بدترین جھوٹا انسان ہو گیا ہے.حضرت مسیح موعودؑ کا اس معیار کو اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کرنا اس زمانہ کے مامور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے اور افسوس کہ آپ کے مخالف بھی ویسی ہی باتوں میں مشغول رہے ہیں.جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف.کاش! لوگ غور کرتے کہ وہی شخص جو بدترین دشمنوں کے نزدیک بھی دعوائے مسیحیت سے پہلے اسلام کا سب سے بڑا خادم اور راستبازی کا ایک بے نظیر نمونہ تھا وہ یک دم اس قدر کیوں بگڑ گیا کہ اس نے خدا تعالیٰ پر افترا کرنا شروع کر دیا.اس دلیل کے متعلق بعض تاریخی حالات قرآن شریف کی اس دلیل کے متعلق بعض تاریخی واقعات
Page 75
حسب ذیل ہیں.ابوجہل کی شہادت ترمذی کتاب التفسیر میں آتا ہے کہ ابوجہل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی جس میں ابوجہل نے کہا اِنَّا لَانُکَذِّبُکَ بَلْ نُکَذِّبُ بِمَاجِئْتَ بِہٖ.ہم تجھ کو جھوٹا قرار نہیں دیتے بلکہ اس تعلیم کی تکذیب کرتے ہیں جو تو لے کر آیا ہے.اس سے ظاہر ہے کہ نبوت کے دعوے کے بعد بھی مخالفین کو یہ دلیری نہ تھی کہ بعثت سے پہلے زمانہ کے متعلق آپ پر کوئی الزام لگائیں.بلکہ شروع شروع میں آپ کو جھوٹا کہنے سے پرہیز کرتے تھے.بعد میں آہستہ آہستہ جھوٹا کہنے لگ گئے.نضر بن حارث کی شہادت نضر ابن الحارث کا واقعہ لکھا ہے (اور یہ ان نو دشمنوں میں سے ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا تھا) کہ ایک دفعہ کفار آپس میں مشورہ کررہے تھے کہ حج کے موقعہ پر باہر سے آنے والے لوگوں کو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہیں گے.ایک نے ان میں سے کہا کہ ہم کہہ دیں گے یہ شخص جھوٹا ہے تو النضر بن الحارث کھڑا ہو گیا اور جوش کے ساتھ کہا قَدْ کَانَ مُحَمّد فِیْکُمْ غُلَامًا حَدَثًا اَرْضَا کُمْ فِیْکُمْ وَاَصْدَقُکُمْ حَدِیْثًا وَاعْظَمُکُمْ اَمَانَۃً حَتّٰی اِذَا رَأَیْتُمْ فِی صُدْغَیْہِ الشَّیْبَ وَجَآءَ کُمْ بِمَا جَاءَ کُمْ بِہٖ قُلْتُمْ سَاحِرٌ لَا وَاللہِ مَاھُوَ بِسَاحِرٍ.یعنی (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے درمیان جوان ہوا.اس کے اخلاق پسندیدہ تھے.تم میں سب سے زیادہ سچا تھا.نہایت امین تھا.وہ اسی حالت میں رہا.یہاں تک کہ تم نے اس کی کنپٹیوں میں سفید بال دیکھے.یعنی وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ گیا.اس وقت جب اس نے اپنی تعلیم کو تمہارے سامنے پیش کیا تو تم کہنے لگے جھوٹا ہے جھوٹا ہے.خدا کی قسم وہ جھوٹا نہیں ہے.یعنی لوگ ہرگز تسلیم نہیں کریں گے کہ وہ جھوٹا ہے.(کتاب الشفاء للقاضی عیاض الباب الثانی الفصل العشرون عدلہ و امانتہ ؐ) اس روایت میں کئی لطیف باتیں بیان ہوئی ہیں.اول یہ کہ اس میں ساری عمر پر بحث کی گئی ہے.یعنی جوانی سے لے کر ادھیڑ عمر تک بچپن کے زمانہ کو چھوڑ دیا ہے.کیونکہ اس پر کوئی عقلمند اعتراض ہی نہیں کیا کرتا.دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی خصوصیات تفصیلاً بیان کی گئی ہیں.تیسری خوبی یہ کہ ایک ایسے دشمن کی طرف سے روایت ہے کہ جو اس کے بعد آپ کے قتل کے واقعہ میں شامل ہوا اور کفر کی حالت میں ہی مارا گیا.چوتھی خوبی اس میں یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیسا گہرا نقش ان کے دلوں پر تھا.کہ ایک دشمن اپنے گھر میں ایسا فقرہ کہتا ہے کہ جو حقیقت کے لحاظ سے ابوبکرؓ جیسے انسان کے منہ سے نکلنا چاہیے.یعنی لا واللہ ماھو بساحر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی نقش اس کے
Page 76
دل پر غالب آگیا.اور اس کی عداوت دب گئی.اور وہ مجبور ہو گیا کہ اس صداقت کا اس قدر پرزور الفاظ میں علانیہ اقرار کرے.حضرت خدیجہؓ کی شہادت بخاری باب بدءالوحی میں حضرت خدیجہؓ کا قول آتا ہے.کَلَّاوَاللہِ مَایُخْزِیْکَ اللہُ اَبَدًا اَنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْکَلُّ وَتَکْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِیْ الضَّیْفَ وَتُعِیْنُ عَلٰی نَوَائِبِ الْحَقِّ.کہ اللہ تجھ کو رسوا نہ کرے گا.کیونکہ تو صلہ رحمی کرتا اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتا، نایاب خوبیوں کو پیدا کرتا، مہمان نوازی کرتا اور مصیبت زدوں کی مدد کرتا ہے.یہ شہادت آپ کی پہلی زندگی کے متعلق آپ کی بیوی کی ہے جو انسان کے اخلاق کی بہترین گواہ ہوا کرتی ہے.ابوسفیان کی شہادت پھر بخاری میں ابوسفیان سے روایت آتی ہے کہ جب ہرقل کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط پہنچا تو اس نے تلاش کروایا کہ عرب کا کوئی آدمی ملے جس سے ہم اس مدعی کے حالات دریافت کریں.آخر ابوسفیان اور اس کا قافلہ جو تجارت کے لئے وہاں گیا ہوا تھا دربار میں حاضر کیا گیا.ہرقل نے ابوسفیان کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو فوراً بتا دینا.اس سلسلہ گفتگو میں ہرقل نے ابوسفیان سے پوچھا فَھَلْ کُنْتُمْ تَتَّہِمُوْنَہٗ بِالْکِذْبِ قَبْلَ اَنْ یَّقُوْلَ مَاقَالَہٗ قُلْتُ لَا.کہ کیا تم لوگ اس کے دعوے سے پہلے اسے جھوٹا سمجھتے تھے.ابوسفیان کہتا ہے میں نے کہا نہیں.ایک روایت میں ابوسفیان نے ذکر کیا ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس جگہ کچھ جھوٹ بول دوں مگر پھر ڈرا کہ ساتھی اس جھوٹ کا اظہار کر دیں گے.(بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الیٰ رسول اللہ ؐ) تمام قبائل قریش کی شہادت اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (الشعراء:۲۱۵) کا حکم ہوا تو آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے.اور تمام قبائل کو جمع کرکے فرمایا اَرَئَیْتَکُمْ لَوْ أخْبَرْتُکمْ أنَّ خَیْلًا بِالوَادِیْ تُرِیْدُ اَنْ تُغِیْرَ عَلَیْکُمْ أکُنْتُمْ مُصَدِّقِیَّ قالُوْا نَعَمْ مَاَجَرَّبْنَا عَلَیْکَ اِلَّاصِدْقًا (بخاری کتاب التفسیر سورہ شعراء) آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ کوہ ابوقبیس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں.کیونکہ ہم نے جب بھی آپ سے معاملہ پڑا ہے آپ کو سچا ہی پایا ہے.مکہ کے حالات سے باخبر لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ مطالبہ بڑا سخت تھا کیونکہ مکہ کے لوگوں کے جانور وادی میں چرا کرتے تھے.اور وہ ایسا علاقہ ہے کہ اس میں لشکر کا چھپ رہنا ناممکن ہے.پس کفار کا کہنا کہ اس ناممکن بات کو بھی تم اگر ہم سے بیان کرو گے تو ہم تمہیں سچا ہی قرار دیں گے.بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
Page 77
کو نہ صرف کفار سچا کہا کرتے تھے بلکہ وہ آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ناممکن قرار دیتے تھے.امیہ بن خلف کی شہادت ایسا ہی ایک اور شدید دشمن آپ کا امیہ ابن خلف تھا.اس کا یہ قول ہے وَاللہِ مَایُکْذِبُ مُـحَمَّدٌ اِذَا حَدَّثَ خدا کی قسم جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بات کرتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے.(بخاری کتاب المناقب باب علامات النبوۃ) یہ بعض ر وایات ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا کا دعویٰ واضح ہو جاتا ہے.پادری ویری کا اعتراض کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے بعض مسیحی مصنفوں نے اس آیت پر اعتراض کیا ہے.چنانچہ ریورنڈ ویری صاحب جو ان میں سے قرآن کریم کے مفسر ہیں اس آیت کے نیچے سیل (ایک دوسرا انگریز جو قرآن کا مترجم تھا) کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ جب اس عمر تک میں تمہارے اندر رہا ہوں اور نہ میں نے کسی سے پڑھا نہ علماء کی مجلس میں بیٹھا اور نہ کبھی شعر یا خطبہ کہا تو اب اس بڑھاپے کی عمر میں میری نسبت کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہ عبارتیں میری اپنی تصنیف ہیں.اس پر پادری ویری صاحب اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں.(۱) کیا یہ عجیب بات نہیں کہ علیؓ کے ساتھ ایک ہی گھر میں پل کر علی تو تعلیم پائے مگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ پائیں.دوم کیا یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ سالوں تک ایک اہم تجارتی کام کرنے کے باوجود انہیں لکھنا نہ آتا ہو.سوم آخری سالوں میں آپؐ یقیناً پڑھنا جانتے تھے.کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپؐ نے حضرت معاویہ کوجو آپ کے کاتبوں میں سے ایک کاتب تھے حکم دیا کہ ’’ب‘‘ سیدھی ڈالو.اور ’’س‘‘ کے دندانوں کو واضح کرو.چہارم انہوں نے اپنی وفات سے پہلے قلم دوات منگائی تھی.جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکھنا جانتے تھے.ویری کی بحث کہ آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ فن کتابت انہوں نے کب سیکھا تھا.بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں اسی طرح سکھایا تھا جس طرح الہام سکھایا تھا.یعنی الہاماً لکھنا پڑھنا بتایا تھا.اور وہ اس کی سند میں اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ (العلق:۲) کو پیش کرتے ہیں.یہ لکھ کر ویری صاحب کہتے ہیں کہ یہ رائے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ان کی رائے ہے اور اس آیت سے ثابت ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا.لیکن یہ امر یہاں سے نہیں نکلتا کہ ان کو یہ علم معجزانہ طور پر سکھایا گیا تھا.اور نہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے پہلے وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے.پھر ویری صاحب لکھتے ہیں.اگر کوئی یہ پیش کرے کہ آپ لکھنے کے لئے کاتب رکھا کرتے تھے تو اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کو لکھنا نہ آتا تھا.کیونکہ کاتبوں کا رکھنا اس وقت کے بڑے بڑے عالموں میں رائج تھا.پھر پادری ویری صاحب خود ہی سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر یہ خیال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ
Page 78
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہ آتا تھا.اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیںکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید میں اَلنَّبِیُّ الْاُمِّیُّ آتا ہے.اس الامی کے لفظ سے مسلمانوں کو دھوکا لگا ہے.کہ آپ ان پڑھ تھے.حالانکہ اس لفظ کے استعمال کی وجہ یہ تھی کہ یہود عربوں کو اُمِّیُّ کہا کرتے تھے.اس لئے اَلنَّبِیُّ الْاُمِّیُّ کے معنی قرآن میں یہ تھے کہ غیر اسرائیلی اور غیر یہودی نبی.پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو غلط فہمی ہوئی کہ آپ اُمِّیْ (ان پڑھ) ہیں اس سے آپ کے دعویٰ کے پھیلنے میں بڑی مدد ملی.کیونکہ یہ قرآن کریم کے معجز نما ہونے کی دلیل بن گیا.حالانکہ مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی پڑھے ہوئے تھے.اس آیت میں لکھنے یا نہ لکھنے کا سوال نہیں یہ ویری صاحب کے اعتراضات کا خلاصہ ہے.اب ان کا جواب حسب ذیل ہے.(۱) آیت کی تفسیر میں میں بتاچکا ہوں کہ اس آیت میں آپ کے پڑھنے لکھنے کی طرف اشارہ نہیں.بلکہ پاکیزہ زندگی کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے.کفار کا یہ سوال نہ تھا کہ آپ اس کتاب کی تحریر کو بدل دیں.بلکہ یہ مطالبہ تھا کہ اس کی تعلیم کو بدل دیں.اور جواب میں خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اسے لکھنا نہیں آتا بلکہ یہ کہا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا تو اس تعلیم کو یہ رسول پیش نہ کرتا اور خدا تعالیٰ اس تعلیم کو نازل نہ کرتا.پس اس جگہ لکھنے یا نہ لکھنے کا سوال ہی نہیں.نہ کفار نے اس جگہ یہ سوال کیا ہے.کہ یہ تعلیم تم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو.کہ اس کے جواب میں لکھنے کا سوال اٹھایا جاتا.ان کا مطالبہ تو یہ تھا کہ اس تعلیم کو بدل دو اور ان کی غرض یہ تھی کہ اگر یہ بدل دیں گے تو ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہوگا نہ بدلیں گے تو ہم قوم کو جوش دلائیں گے کہ دیکھو قومی اتحاد کے لئے یہ اتنی قربانی بھی نہیں کرسکتا.پس جب آیت کے وہ معنی ہی نہیں جو پادری صاحب نے سمجھے ہیں تو اعتراض خودبخود ہی باطل ہو گیا.لیکن بفرض محال اگر یہ ہی سمجھ لیا جائے کہ اس آیت میں آپ کے علم کتابت کے جاننے یا نہ جاننے کا سوال اٹھایا گیا ہے تو بھی پادری صاحب کے اعتراض فضول اور بودے ہیں.حضرت علی ؓ نے آنحضرت ﷺ کے پاس تربیت پائی تھی نہ کہ آپ کے ساتھ پہلی دلیل کہ حضرت علیؓ کے ساتھ ایک ہی گھر میں پل کر کس طرح ممکن تھا کہ علیؓ تو تعلیم پائیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ پائیں کوئی دلیل نہیں.اور صرف اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ریورنڈ ویری صاحب تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں.جو لوگ تاریخ کا تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر میں قریباً انتیس۲۹ سال کا فرق تھا.اس قدر فرق جن کی عمر میں ہو ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ ایک ساتھ ایک گھر میں
Page 79
تربیت پارہے تھے ایک ایسی بعیدازعقل بات ہے کہ جسے غالباً پادری ویری اور ان کی طرح کے چند لوگ ہی جو تاریخ اسلامی سے ناواقف ہیں صحیح سمجھ سکتے ہوں گے.جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہؓ سے ہو چکی تھی اور آپ ان کے گھر میں آ چکے تھے.اور خدیجہؓ نے اپنا سب مال آپ کے سپرد کر دیا تھا.اور آپ ایک مالدار رئیس کی حیثیت پاچکے تھے.پس ایک جگہ دونوں کا تربیت پانا ایک بے دلیل اور خلاف عقل دعویٰ ہے.لطف یہ ہے کہ تاریخ ہمیں پادری صاحب کے اس دعویٰ کے بالکل خلاف بتاتی ہے.تاریخ سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک گھر میں پرورش نہیں پائی.بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی.کیونکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوطالب کی حالت غربت کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بچپن میں ہی اپنے گھر میں لے آئے تھے.اور حضرت علیؓ نے آپ ہی کے گھر پرورش پائی تھی.(حلی ا لایام فی خلفاء الاسلام صفحہ ۱۹۶) پس اگر حضرت علیؓ نے اوائل عمر میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا.اور کوئی عقلمند نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح ممکن ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو تعلیم دلائی تھی تو آپ کے چچا نے آپ کو تعلیم نہ دلائی ہو.تعلیم دلانا تو زمانہ کے حالات اور مربی کے اپنے خیالات پر منحصر ہوتا ہے اور یہاں زمانہ بھی مختلف ہے اور مربی بھی الگ الگ ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کے رائج کرنے کا شوق تھا.آپ نے تعلیم دلائی.آپ کے دادا اور چچا کو اپنے زمانہ کے دستور کے مطابق شوق نہ تھا انہوں نے کوشش نہ کی.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق تعلیم کا یہ حال تھا کہ بڑی عمر میں کئی صحابہ نے تعلیم حاصل کی.حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی عمر میں مدینہ جاکر عبرانی سیکھی.تجارت کرنا تعلیم پر موقوف نہیں دوسری دلیل اگر آپ لکھنا نہ جانتے تو اتنے بڑے اہم تجارتی کام کو کس طرح کرسکتے؟ یہ اعتراض بھی یورپ کی موجودہ حالت پر قیاس کرکے کیا گیا ہے.ایشیا میں اب بھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ بغیر تعلیم کے لوگ بڑے بڑے تجارتی کام کرتے ہیں.تاریخ سے ثابت ہے کہ مکہ کے لوگ لکھنے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے.اور صرف چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے.لیکن تاجر سینکڑوں تھے.تجارت کے لئے قافلے کے قافلے جایا کرتے تھے.پس یہ کہنا کہ جو تاجر جاتے تھے پڑھے ہوئے ہوتے تھے غلط اور قیاس مع الفارق ہے.تجارت کے سفر میں ایک خواندہ غلام آپ کے ہمراہ تھا دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ نے ایک غلام میسرہ نامی جو پڑھا لکھا تھا آپ کے ساتھ کر دیا تھا.پس اس سے یہ دلیل اور
Page 80
بھی کمزور ہو جاتی ہے.حضرت معاویہ کو درست لکھنے کی ہدایت کرنے کی روایت معتبر نہیں حضرت معاویہؓ کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سؔ اور بؔ ٹھیک لکھنے کے لئے کہا.اول تو یہ حدیث ایسی معتبر نہیں.بنوامیہ اور بنوعباس میں اس قدر دشمنی تھی کہ بنوعباس کے زمانہ میں بہت سی ایسی روایات گھڑی گئی ہیں جن میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ علم کی طرف راغب نہ تھے اور کچھ لیاقت و قابلیت نہ رکھتے تھے.لکھنا پڑھنا نہ جاننے کے باوجود بھی ہدایت دی جا سکتی ہے لیکن اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو ایک شخص جو ہدایات دینے اور قرآن لکھوانے کا دیر سے عادی ہو چکا ہو اس کے لئے س اور ب کے لئے ہدایات دینا کچھ مشکل نہیں.اور نہ اس کے لئے پڑھنے کی شرط ہے.بالکل ممکن ہے کسی شخص نے کسی وقت کسی تحریر کے پڑھنے میں دیر کی ہو اور آپ نے پوچھا ہو کہ دیر کی کیا وجہ ہے تو اس نے عرض کیا ہو کہ س کے دندانے ملے ہوئے تھے یا ب لمبی نہ تھی اس لئے جلدی پڑھا نہ گیا.تو آپ نے سمجھ لیا کہ س کے دندانے کھلے ہونے چاہئیں.اور ب لمبی ہونی چاہیے.اور اس وجہ سے معاویہ کو آپ نے ہدایت دی ہو تا کہ تحریر مشتبہ نہ ہوجائے.ہمارے ملک میں عورتیں روٹی پکاتی ہیں.مرد بعض دفعہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ گول دائرہ بناؤ.اب کوئی اس سے یہ سمجھ لے کہ شاید ہم بڑے اچھے روٹی پکانے والے ہیں کیونکہ ہم ہدایت دے رہے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہوگی.پس س کے دندانوں کو کھلا کرنے اور ب کو لمبا کرنے کا حکم دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور لکھنا جانتے تھے.قلم دوات کے منگانے سے لکھنا پڑھنا جاننا ثابت نہیں ہوتا آپ کے قلم دوات منگانے سے استدلال کرنا بھی غلط ہے.کیونکہ قلم دوات حضور ساری عمر منگاتے رہے.جب قرآن مجید لکھواتے تھے تو قلم دوات منگواتے تھے.اس سے یہ کیونکر ثابت ہو گیا کہ آپ لکھنا بھی جانتے تھے.حکم اِقْرَأْ سے بھی یہ مدعا ثابت نہیں ہوتا اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ کی آیت بھی کوئی دلیل نہیں کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے.کیونکہ قرأت کے معنی صرف لکھا ہوا پڑھنے ہی کے نہیں ہیں.بلکہ دوسرے کی بات کو دوہرانے کے لئے بھی یہ لفظ آتا ہے.جو شخص قرآن مجید کو زبانی اچھی طرح پڑھتا ہو اس کی نسبت خواہ وہ اندھا ہو عربی زبان میں کہیں گے ھُوَ یُحْسِنُ قِرَأَۃَ الْقُرْاٰنِ.پس اِقْرَأْ سے لکھا ہوا پڑھنے کا استدلال کرنا کسی صورت میں درست نہیں.صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی قرآنی وحی ہوئی اور حضرت جبریل نے آپ سے اِقْرَأْ کہا تو اس وقت اس نے کوئی تحریر آپ کے سامنے نہیں رکھی تھی پس اِقْرَأْ کے یہ معنی نہیں کہ دیکھ کر پڑھ.بلکہ یہ
Page 81
معنی ہیں کہ جو میں کہتا ہوں اسے دہرا.اُمِّی کا لفظ دھوکہ کا موجب نہیں ہوسکتا ریورنڈ ویری صاحب کا یہ استدلال بھی کہ لوگوں کو امی کے لفظ سے دھوکا لگ گیا ایک عجیب استدلال ہے.حیرت کا مقام ہے کہ ہر وقت آپ کے سامنے رہنے سے تو لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں لیکن ایک امی کے لفظ سے ان کو یقین ہو گیا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے.سوال یہ ہے کہ آیا آپ کے سامنے والوں کو دھوکا لگا تھا یا بعد میں آنے والوں کو؟ اگر کہو سامنے والوں کو تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں کیسے دھوکا لگ سکتا تھا اور اگر کہو بعد والوں کو دھوکا لگا تو سوال یہ ہے کہ دلیل تو یہ دی گئی ہے کہ لوگوں نے یہ خیال کرکے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور پھر بھی ایسی کتاب بنالی ہے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک معجزانہ کمال ہے اور معجزہ کے طور پر قرآن کریم کو صحابہ کے زمانہ سے پیش کیا جاتا ہے.پس اگر اس کے معجزہ ہونے کی یہی دلیل تھی تو صحابہ جو جانتے تھے کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں کس دلیل پر اسے معجزہ قرار دیا کرتے تھے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عرب تو آپ کی زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے.اور وہی عربی زبان کے معجزہ کو سمجھ سکتے تھے.پس ان پر تو اس دھوکے کا کوئی اثر نہ ہو سکتا تھا.اور بعد میں آنے والے عجمی عربی زبان کے کمالات کو سوائے شاذو نادر کے سمجھ نہیں سکتے تھے.پس اس دھوکے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا.پھر اس غلط فہمی سے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا نتیجہ کس نے نکالا؟ اُمِّی کے معنی عربی زبان میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امی کے معنی عربی زبان میں ان پڑھ کے بھی ہیں اور اصل معنی ماں سے نسبت رکھنے والے کے ہیں اور اسی وجہ سے اس کے معنی ان پڑھ کے بھی ہیں کیونکہ وہ ویسا ہی رہتا ہے جیسا کہ پیدا ہوا.اور میرے نزدیک پاکیزہ کے بھی ہیں.کیونکہ نوزائیدہ بچہ پاک ہوتا ہے اور انہی معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے.یہودی لوگ جو عربوں کو امی کہہ کر پکارتے تھے تو حقارت کے طور پر ان کے جاہل ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے.اب کیا یہ بات کوئی عقل مند تسلیم کرسکتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ لفظ اپنے اصلی معنوں میں تو استعمال نہیں ہوا لیکن ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جسے ایک دشمن قوم حقارت کے لئے استعمال کیا کرتی تھی.قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام سمجھ لو پھر بھی کیا عقل اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی اور اپنی قوم کی نسبت اس لفظ کو ان تحقیر آمیز معنوں میں استعمال کرتے.جو یہودیوں میں رائج تھے.
Page 82
اس زمانہ میں علماء کا اپنے کاتب رکھنا ثابت نہیں پادری صاحب کی آخری دلیل کہ اس زمانہ میں علماء کاتب رکھا کرتے تھے ایک اور شدید تاریخی غلطی ہے.پادری صاحب نے عباسی خلافت کے زمانہ کا کوئی واقعہ پڑھ کر اس سے زمانہ جاہلیت پر استدلال کر لیا.حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ عرب میں کوئی علماء ہوتے تھے نہ وہ کاتب رکھا کرتے تھے.یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی تائید میں قومی رواج تو الگ رہا ایک مثال بھی مسیحی مؤرخ نہیں پیش کرسکے.مکہ کے ایک ہی عالم کا ذکر تاریخ میں ہے یعنی ورقہ بن نوفل.اور وہ خود لکھا کرتے تھے ان کا کوئی کاتب نہ تھا.افسوس ہے کہ مسیحی مصنف اپنے تعصب میں تاریخی حقائق بھی اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں.فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ پھر (تمہی بتاؤ کہ) جو اللہ( تعالیٰ) پر بہتان باندھے یااس کے نشانات کو جھٹلائے.اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا.بِاٰيٰتِهٖ١ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ۰۰۱۸ (غرض) یہ یقینی بات ہے کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے.حلّ لُغات.اِفْتَرَآءٌ اِفْتَرٰی فَرْیٌ سے نکلا ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں.اِفْتَرٰی عَلَیْہِ الْکَذِبَ اِخْتَلَقَہٗ (اقرب) اِفْتَرٰی کے معنی یہ ہیں کہ بات اپنے پاس سے بنا کر کسی کی طرف منسوب کر دی.اصل معنی وہی کاٹنے کے ہیں.یعنی جان بوجھ کر ایک بات کاٹ لیتا ہے.اَفْلَحَ اَفْلَحَ فَازَوَ ظَفِرَ بِمَا طَلَبَ.اپنے مقصود کو پالیا.اَفْلَحَ بِالشَّیءِ عَاشَ بِہِ.فلاں چیز کے ذریعہ سے خوش زندگی پائی.اَفْلَحَ زَیْدٌ نَـجَحَ فِی سَعْیِہٖ وَاَصَابَ فِی عَمَلِہٖ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا.(اقرب) مُجْرِمُوْنَ مُجْرِمُوْنَ مُجْرِمٌ کی جمع ہے.اور اَجْرَمَ سے نکلا ہے.اَجْرَمَ کے معنی ہیں اَذْنَبَ گناہ کیا.عَظُمَ جُرْمُہٗ اس کا گنہ بہت بڑا تھا.اَجْرَمَ عَلَیْہِ الْجَرِیْمَۃَ جب کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس پر ظلم کیا.(اقرب) تفسیر.دو قانون الٰہی مدعیان نبوت اور ان کے منکرین کے متعلق اس آیت میں دو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں.ایک تو یہ کہ الٰہی قانون میں دو قسم کے لوگ سزا سے نہیں بچ سکتے.ایک تو وہ جو اپنے پاس
Page 83
سے کلام بنائیں اور اسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کریں.اور دوسرے وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام لانے والوں کا مقابلہ کریں.دوسرے یہ بتایا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ بنانے والے ہوں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے یعنی جس امر کو وہ اپنی بعثت کا مدعا قرار دیتے ہیں اور جو تعلیم لے کر وہ دنیا میں آتے ہیں وہ مدعا پورا نہیں ہوتا.اور وہ تعلیم دنیا میں نہیں پھیلتی.افتراء کے ساتھ کذب کی قید قرآن کریم میں اکثر جگہ افتراء کے ذکر میں کذب کو بطور قید لایا گیا ہے.یعنی جو شخص جھوٹا افتراء کرتے ہیں ان کو فلاں فلاں سزا ملتی ہے.حالانکہ افتراء خود جرم ہے اس کے متعلق میرا یہ خیال ہے کہ اگر افتراء صحیح ہو اور اس میں کذبًا والی شرط نہ پائی جائے تو شاید ایسا شخص اس مقررہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جس کا اس آیت میں ذکر ہے.گو مجرم وہ ضرور ہے اور سزاء ضرور پائے گا.جیسے مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے رؤیا ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو اگر اسے خواب نہ آئی ہوگی تو وہ مفتری ہوگا مگر چونکہ جو بات اس نے بنائی ہے وہ اپنی ذات میں سچی ہے اور اس کے خواب بنانے سے دنیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ یہ اس کا ذاتی جھوٹ ہے اور اس سے اپنا تقویٰ اس نے برباد کیا ہے اس لئے اس آیت کے ماتحت اسے سزا نہیں ملے گی.بلکہ جھوٹ بولنے کی جو عام سزا ہے اس کے ماتحت وہ پکڑا جائے گا.کامیابی کا ذریعہ جماعت نہیں بلکہ اپنے اصل مقصد کو پا لینا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مفتری مفلح نہیں ہوتا.یعنی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا.یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ کوئی جماعت نہیں ملتی.یا یہ کہ اسے دولت حاصل نہیں ہوتی.بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص جو مفتری ہو دولت مند ہو جائے.یا ایک جماعت اسے قبول کرلے کیونکہ کوئی شخص صرف اس مقصد کو لے کر کھڑا نہیں ہوتا کہ وہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا.ہر مدعی کوئی نہ کوئی روحانی مقصد بتاتا ہے.یا شریعت کا چلانا یا پچھلی شریعت کو قائم کرنا.پس جب تک وہ اس حقیقی مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا وہ کامیاب نہیں کہلاسکتا.یہ معیار ایسا زبردست ہے کہ کوئی جھوٹا نبی اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا اور سچے نبیوں کو بھی یہ معیار ہر اعتراض سے محفوظ رکھتا ہے.مثلاً حضرت یحییٰ مارے گئے تو یہ امر ان کے مقصد کے خلاف نہیں.اور وہ غیرمفلح نہیں کہلا سکتے.ان کا مقصد حضرت مسیح سے لوگوں کو شناسا کرادینا تھا.جو پورا ہو گیا.گو وہ مارے گئے.پس ان کی موت ان کے مفلح ہونے کی راہ میں روک نہیں.وہ ایک عالم برزخ تھے.اور لوگوں کی طبائع کو مسیح کی قبولیت کے لئے تیار کرنے کی غرض سے آئے تھے.یہ کام انہوں نے کر دیا.اور یہود اسی زمانہ میں مسیح کی آمد کا انتظار کرنے لگ گئے.چنانچہ ان کی سب جماعت حضرت مسیح ؑپر ایمان
Page 84
لے آئی اور ان کا کوئی الگ سلسلہ باقی نہ رہا.بہائیت کی ناکامی پھر دوسری طرف یہ معیار جھوٹے مدعیوں کے دعوے کو بھی رد کرتا ہے.مثلاً بہاء اللہ کو لے لو.اگر بالفرض ان کو مدعی نبوت و رسالت مان بھی لیا جائے اور ان کے مرید بھی لاکھوں ہوں تب بھی یہ ان کی صداقت کا ثبوت نہیں.کیونکہ ان کا مقصد شریعت اسلامی کو ناقص بتاکر بہائی شریعت کو اس کی جگہ قائم کرنا تھا اور یہ مقصد ایک دن کے لئے بھی اور ایک گھر میں بھی پورا نہ ہوا.بلکہ قرآن مجید پہلے سے بھی زیادہ مقبول ہو رہا ہے.اور بہت سے یورپین بھی جو پہلے اسے جھوٹا سمجھتے تھے اب اسے سچا کہہ رہے ہیں.بہاء اللہ جس شریعت کو منسوخ کرنے آئے تھے وہ تو آج اور بھی زیادہ مقبول ہورہی ہے مگر ان کی اپنی شریعت طاقِ نسیان پر پڑی ہے.اب اگر سارا امریکہ بھی بہائی ہوجائے تب بھی بہاء اللہ اس وقت تک مُفلح نہیں کہلا سکتے جب تک کہ بہائی تعلیم دنیا میں قائم نہ ہوجائے غرض اَفْلَحَ کے لفظ نے سچوں کو اعتراض سے بچا لیا اور جھوٹوں کی کامیابی کی حقیقت کھول دی.وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا اور یہ (لوگ) اللہ (تعالیٰ) کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دیتی ہے اور نہ نفع پہنچاتی يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ١ؕ قُلْ ہےاور کہتے ہیں (کہ )یہ( ہمارے معبود) اللہ کےحضور میں ہمارے شفیع ہیں تو( انہیں) کہہ( کہ) کیا تم اللہ ( تعالیٰ) اَتُنَبِّـُٔوْنَ۠ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ١ؕ کووہ (بات) بتاتے ہوجس کے متعلق نہ آسمانوں میں (پائے جانے کا) اسے علم ہے اور نہ( ہی) زمین میں (کہیں سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۰۰۱۹ اس کے وجود کاکوئی پتہ).وہ پاک ہے اور ان کے شریک ٹھہرانے سے وہ بالا تر ہے.حلّ لُغات.دُوْنَ دُوْنَ نَقِیْضُ فَوْقَ نیچے بمعنی اَسْفَلْ نچلا اور بمعنی اِمَامٌ آگے و بمعنی وَرَآءٌ پیچھے اور بمعنی فَوْقٌ اوپر و بمعنی غَیْرٌ سوائے و بمعنی الشَّرِیْفُ قابل عزت و بمعنی الْخَسِیْسُ حقیر.(اقرب) ھٰؤلٓاء ھٰؤلٓاءِ اسم اشارہ قریب بصیغہ جمع.یہ ذوی العقول کے لئے مخصوص ہے.
Page 85
نَبَأٌ تُنَبِّئُوْنَ باب تفعیل سے فعل مضارع ہے.اس کا مادہ نَبَأٌ ہے.جس کے معنی خبر کے ہیں.کُلیات ابی البقاء میں ہے کہ یہ لفظ کسی معمولی خبر کے لئے نہیں بولا جاتا.بلکہ جس امر کو کسی وجہ سے اہمیت اور خاص وقعت حاصل ہو اسی کے لئے اطلاق پاتا ہے.اور اسی رنگ میں ہر مقام پر قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.(اقرب) سُبْحَانَ سُبْحَانَ اللہِ اَیْ اُبَرِّیُٔ اللہَ مِنَ السُّوءِ بَرَاءَ ۃً.سُبْحَانَ کے معنی عیوب سے پاک سمجھنے اور پاک کرنے کے ہیں.(اقرب) اَشْرَکَ یُشْرِکُوْنَ اَشْرَکَ کا فعل مضارع ہے جس کے معنی ہیں جَعَلَ لَہٗ شَرِیْکًا.کسی کو کسی کا شریک قرار دیا اور حصہ دار ٹھہرایا.(اقرب) تفسیر.شرک کا باعث خدا پراور اپنے نفس پر بد ظنی ہے شرک کا باعث اصل میں انسانی پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھنا ہے.مشرک خدا پر بھی بدظنی کرتا ہے اور اپنے نفس پر بھی.شرک کے عقیدہ کی بنیاد ہی اس اصل پر ہے کہ خدا تعالیٰ تک ہم بغیر واسطہ کے نہیں پہنچ سکتے اور نہ وہ ہم تک بغیر واسطہ کے پہنچ سکتا ہے.اسلام اس تعلیم کے بالکل خلاف ہے.وہ نہ خدا پر بدظنی کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ اپنے نفس کی طاقتوں سے مایوسی کی.خدا تعالیٰ نے بندہ کو اپنے تک پہنچنے کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ اپنے اور اس کے درمیان کسی حائل ہونے والی ہستی کو برداشت نہیں کرسکتا.ایک لطیف دلیل اَتُنَبِّـُٔوْنَ۠ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ میں شرک کے متعلق کیا ہی لطیف جواب فرمایا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے آسمان میں یا زمین میں کوئی شفیع ہوتا تو اس کا اعلان خدا کی طرف سے ہونا چاہیے تھا.عہدہ دار کی تعیین گورنمنٹ گزٹ سے ظاہر کی جاتی ہے.فرمایا بجائے اس کے کہ خدا کی طرف سے علم آتا تم لوگ اعلان کرتے ہو کہ فلاں خدا کا شریک ہو گیا ہے.جبکہ تمام نبی بھی جو صرف پیغام بر ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کھڑے کئے جاتے ہیں.تو شریک جو خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں تمہارے نزدیک ساجھی ہیں.کس طرح تمہارے ہاتھوں بنائے جاسکتے ہیں اور الہامی دلیل سے ان کا عہدہ قائم نہیں کیا جاتا؟ پس معلوم ہوا کہ شریک کا علم پہلے تم کو ہوتا ہے اور تم اس کا علم خدا تعالیٰ کو دیتے ہو.ایک پتھر کو لیتے ہو اور ایک جگہ رکھ کر اسے خدا قرار دے دیتے ہو.یا ایک کمزور آدمی کو لیتے ہو اور اسے خدائی طاقتیں عطا کر دیتے ہو.آسمان اور زمین دونوں کو اس لئے شامل کیا کہ بعض شریک آسمان میں قرار دیئے جاتے ہیں اور بعض زمین میں اس کے بعد سُبْحَانَہٗ سے یہ بتایا کہ انسان کو ایک مقصد کے لئے پیدا کرکے پھر راستہ میں روکیں رکھ دینا اور روکیں بھی ایسی کہ ان کو معلوم کرنے کے لئے کوئی الہامی
Page 86
ہدایت ساتھ نہ ہو یہ ایک کامل ہستی کی شان کے خلاف ہے.اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ اپنا کام آپ باطل کرتا ہے.چونکہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اس لئے وہ اس بات سے بھی بالا ہے اور وہ ایسا نہیں کرسکتا.وَ مَا كَانَ النَّاسُ اِلَّاۤ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا١ؕ وَ لَوْ لَا اور( تمام) لوگ ایک ہی گروہ( بنے ہوئے) تھے پھر انہوں نے آپس میں اختلاف (پیدا) کر لیا.اور جو بات كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۰۰۲۰ تیرے رب کی طرف سے پہلے (بہ صورت وعدہ) آچکی ہے اگر وہ( مانع) نہ ہوتی تو جس (امر) میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کے متعلق ان کے درمیان (کبھی کا) فیصلہ (صادر) کیا جاچکا ہوتا.حلّ لُغات.اُمَّۃٌ اَلْاُمَّۃُ اَلْجَمَاعَۃُ (جماعت، مجتمع گروہ) اَلْجِیْلُ مِنْ کُلِّ حَیٍّ قوم(اقرب) اَلطَّرِیْقَۃُ.طریقہ.اَلدِّیْنُ.مذہب.اَلْحِیْنُ.وقت اَلْقَامَۃُ قد.(اقرب) اِخْتَلَفَ اِخْتَلَفَ ضِدُّ اِتَّفَقَ ایک دوسرے سے اختلاف کیا.زَیْدٌ عَمْرًا کَانَ خَلِیْفَتُہٗ جانشین بنا جَعَلَہٗ خَلْفَہٗ دوسرے کو اپنے پیچھے کر دیا.اَخَذَہٗ مِنْ خَلْفِہٖ پیچھے سے پکڑا.اِلَی الْخَلٓاءِ تَرَدَّ دَاِلَیْہِ (اقرب) بار بار گیا اور آیا.کَلِمَۃٌ اَلْکَلِمَۃٌ اَللَّفْظَۃُ لفظ کُلُّ مَا یَنْطِقُ بِہِ الْاِنْسَانُ جو کچھ بھی کہا اور بولا جائے.(اقرب) قَضٰی قَضٰی بَیْنَ الْخَصْمَیْنِ حَکَمَ وَفَصَلَ فیصلہ کیا.( اقرب) تفسیر.لوگوں کے ایک امت ہونے کے معنی لوگوں کے ایک امۃ ہونے کے کئی معنے ہیں.(۱) ہم نے تو لوگوں کو ابتداء میں ایک ہی راہ پر چلایا تھا پھر وہ بگڑ گئے.جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے تو انسان کے اندر ہدایت کا مادہ رکھا تھا اور صحیح راستہ بھی بتا دیا تھا مگر انسان خود ہی اس راستہ کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چل پڑا.بندہ کو ہدایت کے لئے پیدا کیا گیا ہے نہ جہنم کو بھرنے کے لئے ان معنوں سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ہدایت کے لئے پیدا کیا ہے.تبھی تو اسے ہدایت دی.اگر دوزخ کے لئے پیدا کیا ہوتا جیسا کہ بعض لوگ آیات قرآنی کو نہ سمجھتے ہوئے خیال کرتے ہیں تو ابتداء میں انسانوں کو جہنمی راہ پر چلانا چاہیے تھا.پھر ان میں سے جو نکل کر جنتی بن جاتے انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا.مگر ایسا نہیں ہوا.
Page 87
اتحاد کو مٹانے والا عذاب کا مستحق ہے (۲) لوگ ہمیشہ نبیوں کے ذریعہ سے ایک طریقہ پر قائم کئے جاتے ہیں.ہم نبی بھیج کر انہیں راہ راست پر لاتے ہیں.مگر وہ پھر اختلاف کر بیٹھتے ہیں.اگر ہم نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ عذاب بغیر تنبیہ کے نہ آئے گا تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے.مگر وعدہ ہے.اس لئے ہم پھر نبی بھیجتے ہیں.پھر وہ لوگ ان کو مان کر ان کے ہاتھوں پر جمع ہوجاتے ہیں.اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اختلاف کر بیٹھتے ہیں.ان معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کے ذریعہ سے قائم شدہ اتحاد کو مٹانے والا دنیا کی تباہی کو بلاتا ہے.اس لئے وہ سخت عذاب کا مستحق ہے.(۳) لوگ ہمیشہ ایک ہی راہ اختیار کرتے ہیں.پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کی مخالفت کی اور ان کے ساتھ توافق نہ کیا.اب یہ بھی ویسا ہی کرتے ہیں.اگر ہمارا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ انسان کو ہدایت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور رحم غالب رہے گا تو اس جرم کی وجہ سے ان کا فیصلہ ہی کردیتے.وَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ١ۚ فَقُلْ اِنَّمَا اور وہ کہتے ہیں کہ اس( رسول )پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتارا گیا.اس لئے تو( انہیں) کہہ الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا١ۚ اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَؒ۰۰۲۱ (کہ اس) غیب (کی بات کا علم) اللہ( تعالیٰ) ہی کے پاس ہے.اس لئے تم (اس کا) انتظار کرو میں (بھی )تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں.حلّ لُغات.اَلْغَیْبُ کُلُّ مَا غَابَ عَنْکَ ہر پوشیدہ چیز.اَلسِّرُّ راز.مَاغَابَ عَنِ الْعُیُوْنِ.آنکھوں سے پوشیدہ چیز.(اقرب) تفسیر.خدا کے بھیجے سب نشان ہوتے ہیں اس جگہ مِنْ رَّبِّہٖ بَیِّنَۃٌ کے قائم مقام ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلیل آتی ہے وہ بینہ ہوتی ہے یعنی وہ اپنے مطلب کی طرف خود بلاتی ہے گویا بولتی ہوئی دلیل ہوتی ہے.ہمیشہ سے انبیاء کے دشمن کہتے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی دلیل نہیں اتری.کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ یہ سورۃ تو شروع ہی تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِسے ہوتی ہے.(یعنی یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں) مگر مخالفین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس پر کوئی آیت نہیں اتری.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیات ہر شخص کو نظر نہیں آیا کرتیں.ان کے دیکھنے کے لئے بھی خشیت اللہ کی آنکھ کی ضرورت ہے.ورنہ کس طرح ممکن تھا کہ
Page 88
آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ یہ مطالبہ کرتے کہ اس پر اگر آیات نازل ہوتیں تو کیا اچھا ہوتا.آج بھی بانئے سلسلۂ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف علماء یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی آیت اترتی تو ہماری عقل ماری تھی کہ نہ مانتے.مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی بھی تو عقل نہ ماری ہوئی تھی کہ انہوں نے نہ مانا.ان کے راستہ میں بھی یہی روک تھی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے خوف سے کام نہ لیا.پس ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا.آیت بمعنیٰ عذاب یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ جب کفار کی طرف سے آیت کا مطالبہ ہو تو اس کے معنی عذاب ہی کے ہوتے ہیں.بجز اس جگہ کے جہاں وہ آیۃ کی تشریح کر دیں.پس اس آیت میں ان کی یہ مراد بھی ہوسکتی ہے کہ خدا کی طرف سے اس کی تائید میں کوئی عذاب کیوں نہیں آتا.پیشگوئیوں میں وقت کی تعیین ضروری نہیں ہو تی اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ کے فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشگوئیوں میں وقت کی تعیین کی ضرورت نہیں ہوا کرتی.اگر اس کی ضرورت ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا کہ عذاب کی پیشگوئی کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے.بلکہ ان کے سوال کے جواب میں اس وقت سے ان کو آگاہ کیا جاتا مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا.یہی کہہ دیا ہے کہ وقت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے.جب وہ وقت آئے گا وہ خود حقیقت کو ظاہر کر دےگا.اس آیۃ سے ان لوگوں کو اپنے خیالات کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ پیشگوئی کے ساتھ وقت کی تعیین ہونی ضروری ہے جب ایک امر غیر معمولی طور پر اتفاق اور حادثہ کے شبہ سے بالا رہتے ہوئے پورا ہوجائے تو اس کے ماننے میں کسی سعید انسان کو انکار نہیں ہونا چاہیے.اور وقت کی پخ لگانا صرف ضد اور ہٹ دھرمی کو ظاہر کرتا ہے.دُکھ انبیاء پا رہے ہوتے ہیں اور عذاب کا مطالبہ کفّار کرتے ہیں اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ.کہہ کر کافروں کو جو عذاب کا مطالبہ کرتے تھے نہایت لطیف جواب دیا ہے.کہ عذاب کے جلدی نہ آنے سے گھبراہٹ تو مجھے ہونی چاہیے تھی جو آئے دن تمہارے ظلموں کا نشانہ بن رہا ہوں نہ کہ تم لوگوں کو جو آرام سے گھروں میں بیٹھے ہو.مجھے مارا اور پیٹا جاتا ہے.گھر سے باہر نکلنے سے روکا جاتا ہے مگر میں اطمینان سے انتظار کرتا ہوں اور گھبرا تم رہے ہو کہ عذاب کیوں جلدی نہیں آتا.نادانو! جب میں انتظار کرتا ہوں تو تمہارے لئے انتظار کرنا کیوں دوبھر ہو رہا ہے.
Page 89
وَ اِذَاۤ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا اور جب لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو ہم کسی (قدر اپنی) رحمت (کا مزہ) چکھاتے ہیں تو جھٹ ہمارے لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْۤ اٰيَاتِنَا١ؕ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا١ؕ اِنَّ رُسُلَنَا نشانوں کےمتعلق ان کی طرف سے کوئی( نہ کوئی مخالفانہ) تدبیر ہونے لگتی ہے.تو( انہیں) کہہ (کہ اس کے مقابل پر ) يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ۰۰۲۲ اللہ کی تدبیر (اس سے کہیں) زیادہ جلد( کارگر) ہوا کرتی ہے.(اور) تم جو تدابیر( بھی) کرتے ہو ہمارے فرستادے (اسے) لکھتے (رہتے )ہیں.حلّ لُغات.اَذَاقَ اَذَقْنَا اَذَاقَہٗ سے نکلا ہے جو آگے ذَاقَ سے نکلا ہے.ذَاقَ الْمَکْرُوْہُ.نَزَلَ بِہٖ فَقَاسَاہُ.اس پر مصیبت نازل ہوئی.اور اس نے سہی.وَیُسْتَعْمَلُ الذَّوْقُ فِیْمَا یَحْمَدُوَیَکْرَہُ.اور ذَوْقٌ کا لفظ اچھی اور بری دونوں باتوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے.اَذَاقَہٗ کے معنی ہیں صَیَّرَہٗ یَذُوْقُ.اسے چکھایا یا پہنچایا (اقرب) ضَرَّآءُ اَلضَّرَآءُ اَلشِّدَّۃُ.سختی.اَلنَّقْصُ فِی الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ مال میں یا جانوں میں کمی کا واقع ہونا.اَلزَّمَانَۃُ یعنی آفت و مصیبت.کسی عضو کا کٹ جانا.یا ضائع ہوجانا اور ضَرَّآءُ اسم مؤنث ہے اس کا مذکر کوئی نہیں (اقرب) اَلْمَکْرُ اَلْمَکْرُ اَلْمَغَرَۃُ.دھوکہ.جَزَآءُ الْمَکْرِ.سُمِّیَ بِہٖ کَمَا سُمِّیَ جَزَآءُ السَّیِّئَۃِ سَیِّئَۃً مَجَازًا عَلٰی سَبِیْلِ مُقَابَلَۃِ اَللَّفْظِ بِاللَّفْظِ فریب کے بدلہ کو بھی مکر کہتے ہیں اور اس کا نام مکر اسی طرح رکھا گیا ہے جس طرح سَیِّئَۃ کے بدلہ کو سَیِّئَۃ مجازاً کہتے ہیں.عرب کے عام دستور کے مطابق کسی فعل کے مقابل پر اس کے بدلہ کے ذکر کے لئے بھی اسی فعل کا لفظ استعمال کرلیتے ہیں.(اقرب) مَکَرَاللہُ فُلَانًا جَازَاہُ عَلَی الْمَکْرِ.اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو اس کے مکر کا بدلہ دیا قِیْلَ الْمَکْرُ صَرْفُ الْاِنْسَانِ عَنْ مَقْصَدِہٖ بِحِیْلَۃٍ.مکر کے اصل معنی یہ بھی بیان کئے گئے ہیں کہ کسی شخص کو کسی تدبیر کے ذریعہ سے اس کے مقصد سے دور کر دینا اور ہٹا دینا.وَھُوَنَوْعَانِ مَحْمُوْدٌ یُقْصَدُ
Page 90
فِیْہِ الْخَیْرُ وَمَذْمُوْمٌ یُقْصَدُ فِیْہِ الشَّرُّ اس کی دو قسمیں ہیں ایک محمود جس میں بھلائی مقصود ہوتی ہے دوسری مذموم جس میں برائی مقصود ہوتی ہے.(اقرب) تفسیر.عذاب بھیجنے میں تدریج اور لوگوں کا اس سے فائدہ نہ اٹھانا اس سے دو آیات پہلے فرمایا تھا کہ چونکہ انسان کو ہم نے رحمت کے لئے ہی پیدا کیا ہے اس لئے ہم اپنے عہد کی وجہ سے لوگوں پر رحمت ہی کرتے ہیں.اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ لوگ عذاب مانگتے ہیں مگر باوجود ان کے مطالبہ کے ہم عذاب فوراً نہیں بھیجتے.بلکہ انتظار کے بعد بھیجتے ہیں تاکہ جنہوں نے ہدایت پانی ہے پالیں.اب اس آیت میں فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم عذاب دیر سے بھیجتے ہیں بلکہ عذاب بھیجنے کا ہمارا طریقہ بھی یہی ہے کہ عذاب یک دم نہیں آتا بلکہ کسی قدر عذاب آجاتا ہے پھر ہم اس عذاب کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ عذاب انکار نبوت کی وجہ سے آسکتا ہے.اور آئے گا اور اپنے ناپسندیدہ رویہ اور بے وجہ ظلم سے باز آجائیں.لیکن شریر طبع لوگ پھر بھی نصیحت نہیں حاصل کرتے.بلکہ عذاب کے وقت تو کسی قدر ڈر جاتے ہیں.مگر جس وقت عذاب میں کمی ہوتی ہے معاً پھر ہمارے کلام اور ہمارے نشانات کے خلاف تدابیر اختیار کرنے لگتے ہیں.فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو بہت جلد نافذ ہوجاتی ہے مگر وہ خود ہی اپنی تدبیر کو روکے رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نہ تو ان لوگوں کے کام مجھے بھول سکتے ہیں کہ فوراً بدلہ دینے کی ضرورت ہو اور نہ ان کی سزا پر قابو پانے کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اس وقت سزا دے دوں ورنہ پھر مشکل ہوگی.وہ ہر وقت سزا دے سکتا ہے اور کوئی بات اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہوتی.انسان کا آرام کی گھڑیوں کو ہمیشہ کے لئے سمجھنا اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانی فطرت ایسی ہے کہ جب اسے آرام پہنچے تو وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ اب رحمت ہمیشہ ہی رہے گی حالانکہ اگر آرام کے وقت انسان تکلیف کی گھڑیوں کا خیال کرے تو بہت آرام میں رہ سکتا ہے.افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس گر کو نہ سمجھا اور آج اس ذلت کو پہنچ رہے ہیں.بلکہ اب بھی وہ اس اصل کو یاد نہیں رکھتے اور اپنے روپیہ اور مال کا خیال نہیں رکھتے اور اسراف سے کام لیتے ہیں یا پھر ایسے بخل سے کام لیتے ہیں کہ جو نتیجہ کے لحاظ سے ویسا ہی تباہ کن ہوتا ہے جیسا کہ اسراف.عذاب کے بعد رحمت کے آنے سے لوگوں کا اس عذاب کو بھلا دینا دوسرے اس آیت میں کفار کے پہلے سوال کا جواب بھی دیا گیا ہے.کفار کا سوال تھا کہ اگر یہ سچا ہے تو آیت یعنی عذاب کیوں نہیں آتا.اس کا جواب دیا کہ عذاب تو کئی آچکے ہیں.مگر چونکہ ہم اپنی سنت کے مطابق اس کے بعد رحمت بھیج دیتے ہیں تم لوگ اپنی شقاوت
Page 91
کی وجہ سے عذاب کو بھول جاتے ہو.اور پھر عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہو.افسوس کہ اس مرض میں اس وقت مسلمان بھی مبتلا ہیں.آفت پر آفت ان پر ٹوٹ رہی ہے.لیکن خدا تعالیٰ کی سنت کے مطابق جب رحمت کی ساعت درمیان میں آجاتی ہے تو وہ پھر غافل ہوجاتے ہیں اور اپنی نجات کی فکر سے آزاد ہوجاتے ہیں.اَسْرَعُ مَکْرًا کے معنی قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا میں بتایا ہے کہ تمہاری تدبیروں کا اثر تو نکلتے ہی نکلے گا.مگر خدا کی تدبیریں تمہاری تدبیروں سے پہلے ہی اثر دکھائیں گی.تم جو تدابیر کرتے ہو ان کے نتائج تمہارے خلاف ساتھ ساتھ مترتب ہوتے جاتے ہیں.جوں جوں تم تدبیریں کرتے ہو ہم ساتھ کے ساتھ ان کے توڑ پیدا کرتے جاتے ہیں.لیکن ہماری تدابیر ایسی سریع ہوتی ہیں کہ تمہارے ہوشیار ہونے سے پہلے ان کے نتائج نکل آتے ہیں.عذاب کے وقت ظالموں کے ساتھ بعض نیک کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو ظالم کے ساتھ نیک کیوں پس جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ چند لوگوں کی ہدایت کے لئے لاکھوں شریروں کو بھی تو امن دیا جاتا ہے اگر ظالموں کے ساتھ بعض نیک لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے.مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے اور ایک کے دکھ سکھ میں دوسرے کو بھی ایک حد تک شریک ہونا پڑتا ہے.پس جب عذاب آتا ہے تو جس قوم پر عذاب آتا ہے اس کے ساتھ رہنے والوں کو ان کی معیت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے.اللہ تعالیٰ کا رحمت کو اپنی طرف منسوب کرنا اور ضراء کو نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رحمت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے لیکن ضراء کو نہیں کیا.اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت خدا کی طرف سے آتی ہے اور ضراء انسانی اعمال کے نتیجہ میں آتی ہے.کفار کا خدا کے احسانات کو اس کی مخالفت کا آلہ بنانا اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْۤ اٰيَاتِنَا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم ان پر احسان کرتے ہیں اور وہ الٹے اس احسان کو ہمارے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں.مثلاً ہم اموال وغیرہ انہیں دیتے ہیں تو وہ ان اموال کو ہمارے رسول اور ہماری تعلیم کے خلاف استعمال کرتے ہیں.
Page 92
هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ١ؕ حَتّٰۤى اِذَا كُنْتُمْ وہ (خدائے کریم) وہی ہے کہ جو تمہیں (توفیق دے کر) خشکی اور تری میں چلاتا ہے.یہاں تک کہ جب تم (لوگ) کشتیوں فِي الْفُلْكِ١ۚ وَ جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّ فَرِحُوْا بِهَا میں( سوار) ہوتے ہو اور وہ عمدہ ہوا کے ذریعہ سے ان (لوگوں) کو (بھی )لے کر چل رہی ہو تی ہیں اور وہ ان پر اترا رہے جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّ جَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ ہوتےہیںتو ان پر ایک( تند) تیز ہوا آجاتی ہے.اور ہر طرف سے موج (پر موج) ان پر (چڑھ) آتی ہے.اور وہ مَكَانٍ وَّ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ١ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ سمجھنے لگتے ہیں کہ (اب )وہ ہلاکت (کے منہ) میں آگئے ہیں تو( ایسے وقت میں) وہ اللہ (تعالیٰ) کو اس کے لئے( اپنی) لَهُ الدِّيْنَ١ۚ۬ لَىِٕنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ۰۰۲۳ اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ اے اللہ )اگر تو نے ہمیں اس (مصیبت )سے نجات دی تو ہم ضرورہی( تیرے) شکر گذاروں( کے زمرہ) میں (داخل) ہو جائیںگے.حلّ لُغات.سَیَّرَ سَیَّرَ سَارَ کے باب تفعیل سے ہے اور اس کے معنی چلانے کے ہیں.اور سَارَ کے معنی ہیں چلا.اَلْفُلْکُ اَلْفُلْکُ اَلسَّفِیْنَۃُ.کشتی یُؤَنَّثُ وَیُذَکَّرُ.یہ لفظ کبھی مؤنث استعمال ہوتا ہے اور کبھی مذکر.اور واحد کے لئے بھی اور جمع کے لئے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے.(اقرب) عَصَفَ عَاصِفٌ عَصَفَ یَعْصِفُ عَصْفًا سے نکلا ہے.عَصَفَ الزَّرْعُ جَزَّہٗ قَبْلَ اَنْ یُّدْرَکُ.اس نے کھیت اس کے پکنے سے پہلے کاٹ دیا.عَصَفَتِ الرِّیْحُ تَعْصِفُ عَصَفًا و عُصُوْفًا اِشْتَدَّتْ.ہوا تیز ہو گئی.وَالْعَاصِفُ اَلْمَائِلُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ.ٹیڑھی چیز.(اقرب) ظَنَّ ظَنَّ کے معنی یقین کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور گمان کے بھی.اَلظَّنُّ ھُوَالْاِعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ
Page 93
اِحْتِمَالِ النَّقِیْضِ وَیُسْتَعْمَلُ فِی الْیَقِیْنِ وَ الشَّکٍّ (اقرب) یعنی ظن کے معنی عام طور پر غالب خیال کے ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس کے خلاف کا احتمال بھی ہوتا ہے.اور نیز یہ لفظ یقین کے اور شک کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.اَحَاطَ اَحَاطَ بِالْاَمْرِ اَحْدَقَ بِہٖ مِنْ جَوَانِبِہٖ اسے ہر طرف سے گھیر لیا.اُحِیْطَ بِہٖ دَنَا ھَلَاکُہٗ اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا.(اقرب) اَلدِّیْنُ.الْجَزَاءُ وَالمُکَافَاۃُ.بدلہ اَلطَّاعَۃُ اطاعت.اَلذُّلُّ.ذلت ماتحتی.اَلْحِسَابُ.محاسبہ.اَلْقَھْرُوَ الْغَلَبَۃُ وَالْاِسْتِعْلَاءُ.کامل غلبہ.وَالسُّلْطَانُ وَالْمُلْکُ وَالْحُکْمُ بادشاہت اور حکومت.اَلتَّدْبِیْرُ تدبیر.انتظام وَاِسْمٌ لِجَمِیْعِ مَایُعْبَدُبِہِ اللہُ.تمام وہ طریق جن سے کوئی قوم خدا تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے.اَلْمِلَّۃُ مذہب و کیش.یعنی شریعت.اَلْوَرَعُ.نیکی.اَلْقَضَاءُ فیصلہ (اقرب) اس لفظ کے بعض معانی جو یہاں چسپاں نہ ہوتے تھے چھوڑ دیئے گئے ہیں.تفسیر.سمندر کے سفر کی تمثیل اس آیت میں بتایا ہے کہ سلسلہ سزا اور فضل کا برابر چلتا جاتا ہے.اور دوسری طرف سے بھی شرارت کا جب آرام ہو اور ناقص رجوع کا جب سزا کا وقت ہو.لیکن یہ لوگ کبھی خیال نہیں کرتے کہ جس طرح نرم ہوا ہی کسی وقت سخت ہوکر ہلاکت کا موجب ہوجاتی ہے کہیں یہ فضل ہی ہماری تباہی کی صورت اختیار نہ کرلے.اور معترضین کو خشکی اور تری کے حالات کی طرف توجہ دلائی ہے.اور پھر مثال کے طور پر سمندر کے سفر کو لیا ہے کیونکہ پانی کو الہام الٰہی سے مناسبت ہے اور بتایا ہے کہ سمندروں میں جس طرح نرم ہوا کسی وقت طوفان بن جاتی ہے اسی طرح انبیاء کے مخالفوں کو جو وقفہ ملتا ہے اسے عذاب کا دور ہوجانا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ڈرنا چاہیے کہ یہ سکون کسی سخت طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو.اور بتایا ہے کہ جب ایسا عذاب آتا ہے تو تم لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور تم خیال کرتے ہو کہ تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کی چلتی ہے اور آئندہ اصلاح کے بڑے بڑے اقرار کرتے ہو.لیکن کیا یہ حالت ہمیشہ قائم رہتی ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت میں دیا ہے.ضمیر مخاطب کے بعدضمیر غائب لانے کی وجہ آیت کو شروع خطاب کی ضمیروں سے کیا تھا لیکن اس جملہ میں غائب کی ضمیر استعمال کی ہے.اس میں ایک لطیف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ پہلے حصہ میں چونکہ مومن و کافر سب شامل تھے سب ہی کے لئے خدا تعالیٰ نے خشکی و تری کے سفروں کے سامان پیدا کئے ہیں.اس لئے وہاں تو تم کہہ کر
Page 94
مسلمانوں کو بھی شامل رکھا لیکن اس جگہ یہ بتایا ہے کہ پھر ایک حصہ ناشکرگذاری کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس وجہ سے ضمیر بدل دی اور فرمایا کہ جب انہیں لے کر کشتیاں چلتی ہیں تو پھر وہ یہ نمونہ دکھاتے ہیں کہ عذاب کے وقت تو رجوع دکھاتے ہیں اور فضل کے وقت روگردانی کرتے ہیں.فَلَمَّاۤ اَنْجٰىهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ١ؕ پھر جب وہ انہیں (اس سے) نجات دے کر خشکی پر پہنچاتا ہے تو جھٹ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنےلگتے ہیں يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ١ۙ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ (اے لوگو)تمہارا صرف ورلی زندگی کو چاہنا تمہارے نفسوں پر(وبال بن کر) پڑے گا.پھر ہماری طرف تمہاری الدُّنْيَا١ٞ ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۰۰۲۴ واپسی ہوگی تب جو( کچھ کہ) تم کرتےرہے ہو گے.ہم اس سے تمہیں آگاہ کریں گے.حلّ لُغات.بَغٰی بغٰی یَبْغِیْ بَغْیًا وَّ بُغَاءً وَّبُغْیَةً وَّ بِغْیَۃً.طَلَبَہٗ اسے طلب کیا.ڈھونڈا.اَلْاَمَۃُ زَنَتْ جب لونڈی کے متعلق آئے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس نے زنا کیا.فُلَانٌ عَدَاعَنِ الْحَقِّ.وَاسْتَطَالَ عَلَیْہِ وَظَلَمَہٗ جب کہا جائے فلاں شخص نے بغاوت کی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے انصاف کو چھوڑ کر دوسرے شخص پر ظلم کیا.(اقرب) مَتَاعٌ اَلْمُتَاعُ کُلُّ مَایُنْتَفَعُ بِہٖ مِنَ الْحَوَائِجِ کَالطَّعَامِ وَالبَزِّ وَاَثَاثِ الْبَیْتِ وَالسِّلَعِ وہ تمام اشیاء جن سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا جاتا ہے متاع کہلاتی ہے.جیسے کھانا، گھر کا سامان فروخت کی چیزیں وغیرہ.وَقِیْلَ مَا یُنْتَفَعُ بِہٖ مِنْ عُرُوْضِ الدُّنْیَا قَلِیْلِھَا وَکَثِیْرِھَا مَاسِوَی الْفِضَّۃُ وَالذَّھَبِ اور بعض کے نزدیک دنیا کا سب سامان جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے وہ متاع ہے خواہ تھوڑا ہو خواہ بہت.سوائے سونے چاندی کے.وعُرْفًا کُلُّ مَایَلْبِسُہُ النَّاسُ وَیَبْسُطُہٗ اور عرف عام میں متاع ان کپڑوں کو کہتے ہیں جو انسان پہنتا ہے یا فرش وغیرہ جو بچھائے جاتے ہیں.وَفِی الْکُلِّیَاتِ اَلْمَتَاعُ وَالمُتْعَۃُ مَایُنْتَفَعُ بِہٖ اِنْتِفَاعًا قَلِیْلًا غَیْرُباَقٍ بَلْ یَنْقَضِیْ عَنْ قَرِیْبٍ یعنی کلیات میں ہے کہ مَتَاع اور مُتْعَہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے قلیل فائدہ حاصل کیا
Page 95
جاتا ہو.اور جس کا فائدہ مستقل نہ ہو بلکہ جلدی ختم ہو جائے.اَصْلُ الْمَتَاعِ مَایُتَبَلَّغُ بِہٖ مِنَ الزَّادِ متاع اصل میں وہ زاد ہے کہ جس کے ذریعہ سے منزل مقصود تک پہنچا جائے.(اقرب) تفسیر.شریعت کوئی چٹی نہیں فرماتا ہے کہ مصیبت کے وقت تو تم رجوع کا وعدہ کرتے ہو لیکن جب ہم مصائب کو ٹلا دیتے ہیں تو پھر تم فساد اور ظلم کی راہ اختیار کرلیتے ہو.مگر اس قدر نہیں سمجھتے کہ وہ فساد اور وہ ظلم خود تمہارے ہی خلاف پڑتا ہے.کیونکہ شریعت کے احکام کوئی چٹی نہیں ہیں کہ ان سے بچ کر انسان یہ خیال کرلے کہ میں ایک مصیبت سے بچ گیا ہوں بلکہ وہ تو انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لئے آتے ہیں.پس جو ان سے بچتا ہے اور دور بھاگتا ہے اس کا نقصان خود اسے ہی ہوتا ہے اور جس وقت وہ اپنی کامیابی پر فخر کررہا ہوتا ہے تو مستقبل اس کے بدانجام پر روتا ہے.اللہ تعالیٰ وہی احکام دیتا ہے جو انسان کے لئے نافع ہوں اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اسلام شریعت کو لعنت نہیں بلکہ رحمت قرار دیتا ہے.اور اللہ تعالیٰ صرف وہی احکام دیتا ہے جو انسان کے نفع کے لئے ہوں.پس ان سے بھاگنا خود انسان کے لئے تباہی کا موجب ہوتا ہے.جیسے کوئی شخص طبیب کے نسخہ کے خلاف کرے تو اس کی بیماری بڑھے گی.اور وہ تکلیف اٹھائے گا.انبیاء کے مخالفین کی مادی ترقی مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا سے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ شریعت کو توڑ کر اور نبیوں کی مخالفت کرکے کیوں انسان بعض وقت ترقی بھی کرتا ہے اور اسے فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے؟ جواب یہ دیا ہے کہ بعض اعمال کرنے کے وقت لذیذ معلوم ہوتے ہیں مگر جب کچھ عرصہ کے بعد ان کا نتیجہ نکلتا ہے تو وہ تکلیف دہ ہوتا ہے مثلاً ایک بدپرہیز بیمار جس وقت بدپرہیزی کرتا ہے تو اس وقت تو وہ لذت ہی حاصل کررہا ہوتا ہے اگر اس وقت اسے تکلیف ہو تو وہ بدپرہیزی کرے ہی کیوں؟ لیکن بعد میں جب بیماری بڑھتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے.متاع کے لفظ میں اسراف سے بچنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دنیوی اموال کا نام متاع رکھ کر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے اموال اور سامان درحقیقت زادراہ کے طور پر ہیں.جس طرح وہ شخص جو زادراہ کو ضائع کر دے نقصان اٹھاتا ہے.اسی طرح وہ شخص جو ان اموال کو بجائے اس غرض میں استعمال کرنے کے جس کے لئے وہ پیدا کئے گئے ہیں دوسری اغراض میں خرچ کردیتا ہے.نقصان اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد یعنی لِقَاء الٰہی سے محروم رہ جاتا ہے.
Page 96
اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ اس ورلی زندگی کی حالت (تو )اس پانی کی طرح ہے جسے ہم نے بادل سے برسایا پھر اس کے ساتھ زمین کی فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَ روئیدگی جسے آدمی اور (نیز) چارپائے کھاتے ہیں مل(کر یکجان ہو) گئی یہاں تک کہ جب زمین نے (اس کے الْاَنْعَامُ١ؕ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّيَّنَتْ وَ ذریعہ سے )اپنی کمال درجہ کی زینت کو پا لیا.اور خوبصورت ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ (اب )وہ اس پر ظَنَّ اَهْلُهَاۤ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَاۤ١ۙ اَتٰىهَاۤ اَمْرُنَا لَيْلًا قابو یافتہ ہیں.تو اس پر دن کو یا رات کو( عذاب کے متعلق) ہمارا حکم آگیا اور ہم نے اسے ایسا کر دیا.کہ گویا وہ ایک اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ١ؕ کٹاہوا کھیت ہے گویا (یہاں )کل (کچھ )تھا (ہی )نہیں (غرض) جو لوگ سوچ سے کام لیتے ہیں.ان کے كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ۠۰۰۲۵ لئےہم اسی طرح پر (اپنی ) آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں.حلّ لُغات.الْمَثَلُ الْمَثَلُ الشِّبْہُ وَالنَّظِیْرُ.مشابہ اور نظیر.اَلصِّفَۃُ حالت بیان.اَلْحُجَّۃُ دلیل ثبوت.اَلْحَدِیْثُ بات.اَلْقَوْلُ السَّائِرُ ضرب المثل.(اقرب) اِخْتَلَطَ اِخْتَلَطَ خَلَطَ میں سے باب افتعال کی ماضی ہے.اس کے معنی ہیں اِمْتَزَجَ مل جل گیا.الْجَمَلُ سَمُنَ موٹا ہو گیا.الظِّلَامُ اِعْتَکَرَ سخت تاریک ہو گیا.(اقرب) اَنْعَامُ اَنْعَامُ نَعَمٌکی جمع ہے.اس کے معنی ہیں اَلْاِبَلُ اونٹ.اَلشَّاۃُ بکری وَ قِیْلَ خَاصٌّ بِالْاِبِلِ یعنی بعض کے نزدیک نعم صرف اونٹ کے لئے خاص ہے.قَالَ اَبُوعُبَیْدَۃُ النَّعَمُ اَلْجِمَالُ فَقَط.یُؤْنَّثُ وَ یُذَکَّرُ.ابوعبیدہ کا قول ہے کہ نعم صرف اونٹوں کو کہتے ہیں اور یہ لفظ مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا
Page 97
ہے وَقِیْلَ یُطْلَقُ الْاَنْعَامُ عَلٰی ھٰذِہٖ الثَّلَاثَۃِ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.وَ إِنْ ا نْفَرَدَتِ الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ لَمْ تُسَمَّی نَعَمًا اور بعض کے نزدیک اونٹ گائے بکری ان تینوں کے متعلق جب اکٹھا ذکر ہو تو نعم بول سکتے ہیں.اور اگر اکیلی بکریاں ہوں یا گائے اور بکریاں ہوں یا اکیلی گائے ہوں تو ان کے لئے نعم کا لفظ نہیں بول سکتے.(اقرب) زُخْرُفٌ اَلزُّخْرُفُ الذَّھَبُ سونا کَمَالُ حُسْنِ الشَّیْءِ کسی چیز کی خوبصورتی کا کمال.اَلزُّخْرُفُ مِنَ الْاَرْضِ اَلْوَانُ نَبَاتِھَا.جب زمین کے متعلق یہ لفظ بولیں تو اس کی سبزیوں کے اقسام اور رنگ مراد ہوتے ہیں (اقرب) حَصِیْدٌ اَلْحَصِیْدُ مَقْطُوْعٌ بِالْمَنَاجِلِ.جسے درانتیوں سے کاٹا جائے اَلْمُسْتَأْصِلُ جڑ سے اکھاڑی ہوئی چیز (اقرب) غَنِیَ بِالْمَکَانِ اَقَامَ بِہٖ مکان میں ٹھہرا.لَمْ تَغْنَ نہ ٹھہرا.گویا اس کا وجود ہی نہ تھا.تفسیر.حیات دنیا کی ایک تمثیل یہ ایک تمثیل ہے فرمایا کہ ورلی زندگی کی حالت بالکل پانی کی سی ہے.جیسے پانی آسمان سے اترتا ہے اور اس سے زمین میں رنگارنگ کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں.کوئی تو انسانوں کے کھانے کے کام آتی ہے اور کوئی حیوانوں کے.اس شادابی کو دیکھ کر انسان بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ خدا کے فضل سے ہوا ہے یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ یہ ہماری ہی طاقت اور ہنر سے پیدا ہوا ہے جس وقت اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ان کے اگانے پر قادر ہوں تو اَتَاھَا اَمْرُنَا.اچانک ہمارا عذاب آجاتا ہے جو اس کو تباہ کر دیتا ہے.وہ تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خود اگاتا تھا.لیکن عذاب آنے کے وقت اس کو محفوظ بھی نہیں رکھ سکتا.یعنی جب اقوام میں کبر اور خودپسندی پیدا ہوتی ہے تو ان کی تباہی کا وقت آجاتا ہے.روحانی کلام کی پانی سے تشبیہ اس آیت میں روحانی کلام کو پانی سے مشابہت دی ہے کلام الٰہی جب نازل ہوتا ہے تو دنیا میں تغیرات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں.اور قسم قسم کے علوم نکلنے لگتے ہیں.جیسے قرآن کریم کے نزول کے بعد، اولیاء، محدث، فلسفی وغیرہ ہر قسم کے اہل علم انسان پیدا ہو گئے.یہاں تک کہ جب وہ زمانہ آیا کہ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اِنَّہُمْ قَادِرُوْنَ عَلَیْہَا کہ یہ علوم انہوں نے خود ہی ایجا دکئے ہیں تو وہی مسلمان جو بڑے بڑے ماہر علوم سمجھے جاتے تھے ذلیل ہو گئے.حق تو یہ ہے کہ جو موجب بھی خدا کی طرف سے آتا ہے وہی تغیر پیدا کرتا ہے اور جب وہ موجب نظروں سے دور ہو جاتا ہے تو لوگ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہو رہا ہے.فائدہ اٹھانا فکر پر موقوف ہے فکر کے معنی ہیں ماضی کے حالات کے تسلسل کو ذہن میں قائم رکھنا.پس فرمایا کہ جو لوگ گذشتہ حالات کو ذہن میں رکھتے ہیں وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو اس تسلسل کو قائم نہیں رکھتے وہ فائدہ
Page 98
نہیں اٹھاتے.اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہر اک قوم میں خواہ وہ انبیاء سے کس قدر بھی قریب کیوں نہ ہو اچھے برے آدمی پیدا ہوتے رہتے ہیں.لیکن جب تک خشیت قائم رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل رہتا ہے قوم ہلاک نہیں ہوتی.مگر جب قوم میں خودپسندی اور کبر پیدا ہو جائے تو وہ تباہ کر دی جاتی ہے.پس نبی کا مقابلہ نہ کرو کہ یہ خودپسندی کی علامت ہے اور خودپسند تباہ کر دیا جاتا ہے.خدا کے کلام سے لوگوں کا برے اور بھلے دونوں قسم کے نتائج نکالنا اس جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا ہے اس سے لوگ برے اور بھلے دونوں قسم کے نتائج پیدا کرلیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی غرض اس کلام کے نازل کرنے سے یہی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے حقیقی آرام کی جگہ کو حاصل کرلیں.وَ اللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ١ؕ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى اور اللہ (تعالیٰ)سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے (اسے)ایک سیدھی راہ پر چلا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۰۰۲۶ (کر منزل مقصودپر پہنچا) دیتا ہے.حلّ لُغَات.سَلَامٌ اَلسَّلَامُ اس کے معنی پہلے آچکے ہیں.دَارُالسَّلَامِ جنت کو بھی کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.اللہ پر توکل سلامتی کا موجب ہے اللہ پر توکل کرنے والے کی حالت مستقل ہوتی ہے.سب اشیاء اس کی سلامتی چاہتی ہیں.کامل مطیع کے لئے لوگ دعائیں کرتے ہیں.کیونکہ وہ دنیا کے لئے مفید ہوتا ہے.سلام کے معنی اطاعت کے بھی ہیں.اس صورت میں معنی یہ ہوئے کہ اس کو فرمانبرداری کے مقام پر کھڑا کر دیتا ہے یعنے اللہ تعالیٰ اسے حال سے نکال کرمقام تک لے آتا ہے.اور چونکہ سلام کے معنی جنت کے بھی ہیں اس لئے یہ معنی بھی ہوئے کہ اس کو جنت کا وارث کر دیتا ہے اور سلام چونکہ خدا کا نام بھی ہے اس لئے دارالسلام تک پہنچانے کے یہ معنی بھی ہوئے کہ اس کو اپنے لقا کا وارث کر دیتا ہے.صراط مستقیم کے لفظ میں جلد کامیاب ہونے کی طرف اشارہ ہے وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ یعنی جلد سے جلد اسے کامیاب کر دیتا ہے.کیونکہ سیدھا راستہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے.یہ انبیاء اور اولیاء کا
Page 99
مقام ہے.بعض کو آواز دیتا ہے اور بعض کے پاس آپ آ کر انہیں ساتھ لے جاتا ہے.یہ موہبت کا مقام ہے.لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَ زِيَادَةٌ١ؕ وَ لَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے نیکو کاری اختیار کی بہترین انجام ہو گا اور (اس پر ) مزید(انعامات بھی) اور ان کے قَتَرٌ وَّ لَا ذِلَّةٌ١ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ١ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۰۰۲۷ چہروں پر نہ غبار چھائے گا اور نہ ذلت (کے آثار ہو ں گے) یہ (لوگ) جنت (میں رہنے) والے ہیں.وہ اس میں رہا کریں گے.حلّ لُغَات.حُسْنٰی اَلْحُسْنٰی ضِدُّ السُّوْأَی بدی کے مقابل کی حالت.اَلْعَاقِبَۃُ الْحَسَنَۃُ.اچھا انجام اَلظَّفَرُ.فتح.اَلشَّحَاذَۃُ.چستی اور ہوشیاری اَلنَّظْرُاِلَی اللہِ.ا للہ تعالیٰ کی رؤیت.(اقرب) رَھِق رَھِقَ یَرْھَقُ.رَھْقًا سَفِہَ بیوقوفی کی.رَکِبَ الشَّرَّ وَالظُّلْمَ برائی اور ظلم کا مرتکب ہوا.غَشِیَ الْمَحَارِمَ ناجائز کام کئے.کَذَبَ جھوٹ بولا.عَجِلَ جلدی کی.رَھِقَ فُلَانًا غَشِیَہٗ وَلَحِقَہٗ.اس کے پاس گیا.اور اس سے جاملا.کہتے ہیں رَھِقَتِ الْکِلَابُ الصَّیْدَ کتوں نے شکار کو جالیا.اور بعض کہتے ہیں دَنَامِنْہُ.سَوَاءٌ اَخَذَہٗ اَمْ لَمْ یَأْخُذْہُ قریب ہو گیا.خواہ اسے پکڑسکا ہو یا نہ.(اقرب) اَلْقَتَرُ اَلْقَتَرُاَلْغَبَرَۃُ.غبار (اقرب) اَلدُّخَانُ السَّاطِعُ مِنَ الشِّوَاءِ وَالْعُوْدِ وَنَحْوِھُمَا.جس چیز کو بھونا جائے.اس کا دھواں یا لکڑی کا یا ایسی ہی اور چیزوں کا دھواں.(مفردات) اَلذِّلَّۃُ اَلذِّلَّۃُ ذَلَّ یَذِلُّ ذُلًّا.ضِدُّ صَعُبَ یُقَالُ ذُلَّتْ لَہٗ الْقَوَا فِی سَہُلَتْ.ذَلَّ مشکل یا سخت ہوا کے مخالف معنی دیتا ہے.چنانچہ کہتے ہیں ذَلَّتْ لَہٗ الْقَوَا فِیْ یعنی قوافی اس کے ذہن میں آسانی سے آتے گئے (اقرب) ذلیل کو ذلیل اس لئے کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر ظلم کرنا لوگوں کے لئے آسان ہوتا ہے.تفسیر.اَلْحُسْنٰی کے معنی لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا کے معنی یہ ہوئے کہ مومنوں کا انجام نیک ہوگا.ان کو کامیابیاں ملیں گی.اللہ تعالیٰ ان کے اندر چستی اور تیزی پیدا کر دےگا.وَزِیَادَۃٌ یعنی خود خدا ان کو مل جائے گا.اور وہ ہر قسم کی ذلت اور بدنامی سے محفوظ ہوں گے.اور لوگوں سے دبیں گے نہیں یعنی یہ نہیں ہوگا کہ غلاموں کی طرح لوگوں کی نقل کریں بلکہ ان کو اللہ ایسا بنائے گا کہ لوگ ان کی نقل کریں گے.
Page 100
وَ الَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا١ۙ وَ تَرْهَقُهُمْ اور جنہوں نے بدیاں کی ہوں گی (ان کے لئے) بدی کا بدلہ اس (بدی) کے برابر ہو گا اور انہیں ذلت پونہچے گی.ذِلَّةٌ١ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ١ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغْشِيَتْ اور کوئی بھی انہیں اللہ (کے عذاب) سے بچانے والا نہیں ہو گا (اور ان کی حالت ایسی ہو گی) وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا١ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ گویا ان کے مونہوں پر رات کے کئی (کئی) تاریک حصے ڈال دیئے گئے ہیں.یہ (لوگ) النَّارِ١ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۰۰۲۸ آگ (میں رہنے) والے ہیں وہ اس میں رہا کریں گے.حلّ لُغَات.عَاصِمٌ عَاصِمٌاسم فاعل ہے عَصَمَ سے.عَصَمَ الشَّیْءَ.مَنَعَہٗ روک کر محفوظ کر دیا.حَفِظَہٗ حفاظت کرکے بچا لیا.قِطَعٌ اَلْقِطَعُ اَلْقِطْعَۃُ مِنَ الَّیْلِ رات کا ایک حصہ اور قِطْعَۃٌ کی جمع بھی ہے جس کے معنی ہیں اَلْحِصَّةُ مِنَ الشَّیْ ءِکسی چیز کا کوئی ایک حصہ.خَلَدَ خَالِدُوْنَ خَلَدَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے خَلَدَ بِالْمَکَانِ وَاِلَی الْمَکَانِ.اَقَامَ رہ پڑا.(اقرب) تفسیر.بدی کی سزا بدی سے زیادہ نہیں ملے گی ایک تو اس جگہ یہ بتایا ہے کہ گو نیکی کی جزاء عمل سے زیادہ ملتی ہے.مگر بدی کی جزا اللہ تعالیٰ عمل سے زائد نہیں دیتا.بلکہ اس کے مطابق دیتا ہے.خدا کے قانون توڑنے کا نتیجہ دوسرے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قانون توڑنے والے اعلیٰ ہمتوں سے محروم ہوتے ہیں.اور صرف نقال رہ جاتے ہیں.خود ان میں اقدام اور ایجاد کی طاقت نہیں رہتی.ان کے نزدیک تمام ترقیات کی جڑھ دوسروں کی نقل ہوتی ہے.ان کی امیدوں میں کبھی اس خیال کو جگہ نہیں ملتی کہ وہ دنیا کی راہ نمائی کریں اور لوگ ان کے پیچھے چلیں.ایسا گر اہوا بغیر بیرونی دستگیری کے اٹھ نہیں سکتا تیسرے یہ بتایا ہے کہ ایسی گری ہوئی حالت سے انسان
Page 101
خود نہیں اٹھ سکتا.بیرونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے.لیکن یہ لوگ چونکہ خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کرلیتے ہیں اس لئے بیرونی مدد سے بھی محروم رہ جاتے ہیں.چوتھے یہ بتایا کہ بدی آخر ظاہر ہو کر رہتی ہے اور ظلم چھپ نہیں سکتا.پس دنیا بھی ان کی کمزوریوں سے واقف ہوجاتی ہے.نیز اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے مظالم اور بدیوں سے نہیں بچتے تو کم سے کم اس امر کا ہی خیال کریں کہ یہ اپنی ذلت کا سامان پیدا کررہے ہیں.وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اور( اے لوگو!اس دن کو یاد کرو)جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے.پھر جنہوں نے شرک کیا (ہوگا) انہیں ہم مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَ شُرَكَآؤُكُمْ١ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ کہیں گے (کہ پرے ہٹ کر) اپنی جگہ پر( کھڑے رہو)تم بھی اور تمہارے(بنائے ہوئے خدائی کے )حصہ دار شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ۰۰۲۹ (بھی )پھر ہم ان میں آپس میں (بھی) جدائی ڈال دیں گے اور ان کے (بنائے ہوئے خدا کے) شریک(انہیں ) کہیں گے (کہ) تم ہماری عبادت (تو ہر گز )نہیں کرتے تھے.َ حلّ لُغَات.مَکَانَکَ مَکَانَکَ یہ محاورہ ہے.اس کے معنی ہیں اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو.زَیَّلَہٗ زَیَّلَہٗ فَرَّقَہٗ پراگندہ کر دیا.(اقرب) تفسیر.اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان اجتماع کا ذکر فرمایا ہے جو ایک دن سب صداقتوں کے ظاہر کرنے کا موجب ہوگا.مگر جس کا سمجھنا اس دنیا میں بھی عقل خداداد سے آسان اور سہل ہے.یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں ان شرکاء کا ذکر ہے جنہیں لوگوں نے زبردستی ان کے علم کے بغیر خدا تعالیٰ کا شریک مقرر کر چھوڑا ہے جیسے ملائکہ یا حضرت کرشن.رامچندر، عیسیٰ علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین سید عبدالقادر جیلانی وغیرھم رضی اللہ عنہم.کیونکہ اگلی آیت سے ثابت ہے کہ وہ شرکاء خدا تعالیٰ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے.کہ انہیں اس شریک بنانے کے فعل سے بالکل بے خبری تھی.
Page 102
زَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ کے معنی زَيَّلْنَا بَيْنَهُمْسے بھی اس جگہ یہی مراد ہے کہ اس موقع پر ثابت ہو جائے گا کہ یہ حضرات ان مشرکوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھتے تھے.اور ان کی طرف منسوب ہونے والی جماعتیں جو شرک میں مبتلا تھیں جھوٹ سے کام لے رہی تھیں.پہلے اپنی اپنی جگہ کھڑا ہونے کا حکم بتایا ہے پھر تفرقہ کا.اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے مشرکوں کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کا موقع دیا جائے گا.جب ان کا دعویٰ بے دلیل رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو معبود بنایا جاتا تھا بری قرار دے کر الگ کر دے گا اور اس وقت وہ لوگ خوشی سے اپنی براء ت کا اظہار کریں گے.اس جگہ شرک کے بانی معبودان باطلہ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ اگر یہ سوال ہو کہ اس جگہ معبودوں سے مراد اگر وہ ہیں جو عبادت سے بے خبر ہیں تو ان معبودوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جو خود شرک کے بانی ہوتے ہیں.تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگ خود مشرک ہیں.اور اس وجہ سے مشرکین میں ان کا ذکر آگیا ہے.اس جگہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول کریمؐ کے مخالفین جو شرک کے عقیدہ کو اس دلیل کے ذریعہ سے ثابت کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء اور اولیاء اس کی تائید میں ہیں درست نہیں.اور اس کا رد یوں کیا ہے کہ ان کی تائید کا ثبوت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے.وہ لوگ ہرگز اس کی تائید میں نہیں ہیں.یہ تمہارے اپنے منہ کے دعوے ہیں.فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًۢا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ پس تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان (خود) اللہ (تعالیٰ) کافی گواہ ہے.عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ۰۰۳۰ ہم تمہاری پرستش سےیقیناً بے خبر تھے.تفسیر.یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب نقشہ کھینچا ہے.فرماتا ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے اور شرکاء اور مشرکین کو کہیں گے کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو.وفات مسیح یہ آیت حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قیامت تک ان لوگوں کے افعال سے جو انہیں خدا کا شریک قرار دیتے ہیں ناواقف ہوں گے لیکن اگر ان کو زندہ تسلیم کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ وہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ قیامت
Page 103
میں نعوذباللہ من ذٰلک جھوٹ بولیں گے کہ مجھے تو خبر بھی نہیں کہ یہ لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرتے تھے.هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّاۤ اَسْلَفَتْ وَ رُدُّوْۤا اِلَى اللّٰهِ (تب)وہاں ہر ایک شخص جو کچھ اس نے (اپنے لئے) بویا ہوگا اس کا امتحان کرے گا اور انہیں ان کے سچے مالک اللہ تعالیٰ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَؒ۰۰۳۱ کیطرف لوٹا (کر )لایا جائے گا.اور جو کچھ وہ (اپنے پاس سے) گھڑتے تھے وہ(سب) انہیں بھول جائے گا.حلّ لُغات.بَلَاءٌ بَلَاہُ یَبْلُوْہُ بَلَاءً وَ بَلْوًا.جَرَّبَہٗ وَاَخْتَبَرَہٗ.اس کا تجربہ کیا اور اس کی حقیقت معلوم کی.(اقرب) مَوْلٰی اَلْمَوْلٰی اَلْمَالکُ.مالک.اَلْمُعْتِقُ آزاد کرنے والا.الصَّاحِبُ.ساتھی.آقا اَلْحَلِیْفُ.معاہد.اَلرَّبُ.رب.اَلْوَلِیُّ کارساز.اَلْمُنْعِمُ.محسن.اَلْمُحِبُّ محبت کرنے والا.اَلْقَرِیْبُ.رشتہ دار.(اقرب) حَقٌّ اَلْحَقُّ ضِدُّ الْبَاطِلِ جھوٹ کے خلاف چیز یعنی سچ.اَلْاَمْرُالْمَقْضِیُّ ہوکر رہنے والی بات.اَلْعَدْلُ انصاف.اَلْمُلْکُ.مالکیت.اَلْمَوْجُوْدُ الثَّابِتُ.موجود اور ثابت شدہ چیز.اَلْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ شک کے بعد یقین کا آنا.اَلْمَوْتُ موت.(اقرب) ضَلَّ ضَلَّ یَضِلُّ ضِدُّ اِھْتَدٰی یعنی ہدایت کے خلاف حالت پر ہو گیا.اور دین اور حق کو نہ پایا.ضَلَّ عَنْہُ یَضِلُّ لَمْ یَھْتَدِ اِلَیْہِ.اس طرف راہ نہیں پائی.ضَلَّ یَضَلُّ (ضاد کی زبر سے) فُلَانٌ الطَّرِیقَ.وَ عَنِ الطَّرِیْقِ.لَمْ یَھْتَدِ اِلَیْہِ.راستہ نہ پایا.یہی معنی ہوتے ہیں.جب داریا منزل یا ہر اپنی جگہ پر قائم رہنے والی چیز کا اس کے بعد مذکور ہو.ضَلَّ الرَّجُلُ فِی الدِّیْنِ ضَلَالًا وَضَلَالَۃً.ضِدُّ اِھْتَدٰی.اس شخص نے دین کے معاملہ میں درست راہ نہیں پائی.ضَلَّ فُلَانٌ اَلْفَرَسَ.اس کا گھوڑا کھویا گیا.ضَلَّ عَنْ کَذَا ضَاعَ.ضائع ہو گیا.ضَلَّ الْمَآءُ فِی اللَّبَنِ خَفِیَ وَ غَابَ.پانی دودھ میں مل گیا.اور غائب ہو گیا.ضَلَّ فُلَانٌ فُلَانًا نَسِیَہٗ.اس شخص کو بھول گیا.ضَلَّ النَّاسِی غَابَ عَنْہُ حِفْظُ الشَّیْ ءِبھول گیا.اس کے ذہن سے بات نکل گئی.ضَلَّ سَعْیُہُ عَمِلَ عَمَلًا لَمْ یَعُدْ عَلَیْہِ نَفْعُہٗ.ایسا کام کیا کہ جس کا اسے کوئی نفع نہ ہوا.(اقرب) تفسیر.بتایا کہ ہر کام کی حقیقت اس کی سب کیفیات کے ساتھ اسی دنیا میں معلوم نہیں ہوتی.بعض اشیاء
Page 104
کی حقیقت بالکل اور بعض کی پورے طور پر اگلے جہان میں ہی کھلے گی.اور اس وجہ سے اصل فیصلہ بھی وہیں ہوگا.اور جو اصل مالک ہے وہ فیصلہ کرے گا.ا ور بوجہ حقیقت کے کھل جانے کے سب جھوٹ بھول جائیں گے.مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ کہہ کر ایک تو ان تمام معانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اس لفظ مولا کے ہیں.اور دوسرے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ عادل قائم بذاتہ اور منعم خدا کو چھوڑ کر کہاں جاسکتے ہیں.اور ایسی ہستی کے عذاب سے کیونکر بچ سکتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے؟ ضَلَّ عَنْہُمْ کے معنی ضَلَّ عَنْهُمْ میں دو باتیں بتائی ہیں ایک تو یہ کہ وہ خود اپنے اعمال کو بھول جائیں گے کیونکہ جب انسان کو اپنے قصور کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہے.دوسرے یہ کہ ان اعمال کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا.قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ تو (ان سے) کہہ(کہ بتاؤ) آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے.یا (یہ کہ) السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ کانوں اور آنکھوں پر کون قابو رکھتا ہے اور کون (ایک)مردہ (چیز) میں سے زندہ (چیز) نکالتا اور زندہ (چیز) الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ١ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ۠ اللّٰهُ١ۚ میں سے مردہ (چیز) نکالتا ہے اور کون ( اس) امر کا انتظام کرتا ہے.اس پر وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ(تعالیٰ کرتاہے) فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ۰۰۳۲ تب (انہیں)کہہ(کہ پھر وجہ)کیا (ہے کہ) پھر (بھی )تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے.تفسیر.اس آیت میں زبردست دلائل توحید بیان ہونے کا عیسائی مصنفین کی طرف سے اقرار چند ہی ایسی جگہیں ہیں جہاں عیسائی مفسروں نے تعریف کی ہے.ان مقامات میں سے ایک یہ بھی ہے.ویری صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت میں توحید کی تائید میں بہت زبردست دلیلیں دی گئی ہیں.اور لکھا ہے کہ اسلام کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ تعلیم ہے.لیکن تعجب ہے کہ اسی منہ سے پھر پادری صاحبان اسلام کی کامیابی
Page 105
کو تلوار اور لالچ کی طرف منسوب کرتے ہیں.اور کبھی اس کی بزعم خود گری ہوئی اخلاقی تعلیم کی طرف.زمین اور آسمان دونوںسے رزق آتا ہے اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان دونو سے رزق آتا ہے یعنی ایک جگہ کا رزق کافی نہیں ہوتا.اگر پانی برستا رہے اور زمین میں اگانے کی طاقت نہ ہو تو یہ کافی نہیں.اسی طرح اگر پانی نہ برسے یا اس کے برسنے میں دیر ہوجائے تو زمین کی اگانے کی طاقت کافی نہیں ہوتی.اسی طرح خالی عقل انسان کی روحانی ہدایت کے لئے کافی نہیں.انسانی دماغ زمین کے مشابہ ہے جب تک اس پر الہام کی بارش نہ برسے وہ کبھی بھی روحانی روئیدگی جو روحانی غذا کا کام دے پیدا نہیں کرسکتا.پس تم لوگ کس طرح دعویٰ کرسکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے الہام کے بغیر آپ ہی آپ تم خدا تعالیٰ کو پا لو گے.عقل بے شک ضروری شیئے ہے مگر جس طرح آنکھ بغیر سورج کی روشنی کے نہیں دیکھ سکتی وہ بھی بغیر الہام کے صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتی.جس نے کان اور آنکھیں دی ہیں ممکن نہیں اس نے ان کی اصل غرض کو پورا کرنے کا انتظام نہ کیا ہو پھر فرمایا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے.اگر ان کا کوئی اور مالک ہو اور ہدایت دینا کسی اور کا کام ہو تو بے شک تم کہہ سکتے ہو کہ ہدایت دینے والے نے پرواہ نہیں کی.اور روحانی کانوں اور آنکھوں کے لئے ان کا کام مہیا نہیں کیا.لیکن جس نے کان اور آنکھیں دی ہیں اگر اسی کا کام ہدایت دینا ہے تو کیا یہ بے وقوفی کی بات نہیں ہوگی کہ وہ کان اور آنکھیں تو پیدا کرے لیکن جو کام ان سے لینا ہے اس کا انتظام وہ نہ کرے؟ جب وہ مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں مردہ دلوں کو دوبارہ زندگی حاصل کرنے کا موقع نہ دے اسی طرح فرماتا ہے دیکھو کون زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کررہا ہے.یعنی اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے پیدا ہورہے ہیں.یا مردوں سے زندہ نکل رہے ہیں.زمین میں کھاد ڈالتے ہیں جو فضلہ یعنی مردہ چیز ہوتی ہے لیکن اس سے سبز کھیتی نکل آتی ہے.اسی طرح سبز کھیتی فضلہ بن کر مردہ ہو جاتی ہے.جب یہ کام تمہیں نظر آرہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ مردوں سے زندے اور زندوں سے مردے نکل رہے ہیں تو تم کس طرح امید کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ انکار پر فوراً لوگوں کو سزا دے دے.اور اصلاح کا موقع نہ دے؟ جب ایک بظاہر مردہ چیز سے زندگی کے سامان پیدا ہونے لگتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ایک مردہ دل سے کسی وقت روحانی زندگی کا چشمہ نہ پھوٹ پڑے؟ اور جب یہ امکان باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ لوگوں کو ڈھیل دے تاکہ جو لوگ زندہ ہونے والے ہیں وہ زندہ ہو جائیں؟ پھر فرماتا ہے دیکھو وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ.کون تدبیر کررہا ہے.تمام کام کون چلاتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ.پھر کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جس کے سپرد کام کاچلانا ہو وہ اسے تباہ کر دے؟ مشین پر کام کرنے کے لئے جو آدمی مقرر ہوتا ہے وہ
Page 106
مشین کو چلایا کرتا ہے یا تباہ کرتا ہے؟ کوئی دانا اپنی چیز کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا.بلکہ اس سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے.پس ان سے پوچھو کہ خدا تعالیٰ اس کارخانۂ عالم کو جس میں اس کی قدرت کا ظہور ہورہا ہے کیوں جلدی اور عجلت سے تباہ کردے؟ اسے تو اس کارخانہ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے.نہ کہ تباہ کرنے کی.یہ اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جب انذار کی خبر دی گئی تھی تو کیوںوہ فوراً پوری نہیں کی گئی؟ خدا تعالیٰ کے رحم سے فائدہ اٹھاؤ اِتَّقَا کے معنی ہیں کسی کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ بنانا.پس اَفَلَا تَتَّقُوْنَ کا یہ مطلب ہے کہ صداقت کے ان اصول کو دیکھ کر تم خدا کو اپنا محافظ کیوں نہیں بناتے.یعنی جب تمام قانونِ قدرت میں رحم کا اور ڈھیل کا پہلو غالب نظر آتا ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے صلح کرنے کی کوشش کرتے نہ یہ کہ بار بار عذاب پر زور دیتے.رزق، سمع بصر ،موت و حیات اور تدبیر امر کا تعلق اور ترتیب اس آیت کی ترتیب پر غور کرو کیسی بے نظیر ہے! اول رزق کا ذکر فرمایا ہے جو بقائے حیات کا موجب ہوتا ہے.پھر کان اور آنکھ کا ذکر کیا ہے جو عقل کا ذریعہ ہیں.پھر موت اور حیات کا ذکر کیا ہے جو قوت عملیہ پر دلالت کرتی ہے.جو عقل کے بعد آتی ہے.پھر تدبیر کا ذکر کیا ہے جس کی اعمال کے شروع کرنے پر ضرورت ہوتی ہے.کیونکہ تدبیر کے معنی ہی یہ ہیں کہ مختلف اعمال میں صحیح نظام قائم رکھا جائے.غرض انسان کی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے جن چار ذرائع کی ضرورت ہے ان چاروں کو علی الترتیب پیش کیا ہے.اور پوچھا ہے کہ بتاؤ کہ کوئی نادان ایسا ہوگا کہ جو حیات پیدا کرے پھر احساس پیدا کرے.پھر قوت عملیہ پیدا کرے.پھر اعمال کے لئے ایک نظام مقرر کرے اور پھر یہ سب کچھ پیدا کرکے انسان کو چھوڑ کر الگ ہو جائے اور ان اسباب کو کسی خاص مقصد کے لئے لگانے کی ہدایت نہ دے.ہر اک جو ذرہ بھر بھی عقل رکھتا ہو سمجھ سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہوسکتا.ان ضروریات اور سامانوں کے پیدا کرنے کا اصل مقصد جو ہستی ان چار امور کو پیدا کرے گی وہ ضرور ان امور کے لئے کوئی خاص مقصد بھی مقرر کرے گی.پس یہ امر خیال میں بھی نہیں لایا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ بغیر رہنمائی کے بندوں کو چھوڑ دے گا.اور الہام اور وحی سے ان کو ممتاز نہ کرے گا.یا پھر ہدایت کا موقع دینے سے پہلے ہی ان کو ہلاک اور تباہ کر دے گا.اگر اس قدر جلد عذاب دینا اسے مطلوب ہوتا تو اس قدر لطیف سلسلہ کو پیدا ہی کیوں کرتا؟ اس آیت میں شرک کا رد بھی ہے اور بتایا ہے کہ جب اصولی طور پر تم تسلیم کرتے ہو کہ رزق دینے والا قوائے انسانیہ پیدا کرنے والا حیات و ممات پیدا کرنے والا اور تدبیر امور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر کن وجوہ پر تم
Page 107
یہ دعویٰ پیش کرتے ہو کہ فلاں فلاں کام فلاں معبود باطل نے کیا ہے.جب یہ تمام امور خدا تعالیٰ ہمیشہ سے کرتا ہے تو ان امور کے خاص خاص ظہوروں کو تم کس طرح کسی اور ہستی کی طرف منسوب کرسکتے ہو.خدا تعالیٰ جب ہمیشہ سے مردوں سے زندے پیدا کرتا چلا آیا ہے تو کس طرح یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں بچہ فلاں فلاں بت نے یا فلاں معبود نے دیا ہے.جو ہمیشہ سے دیتا چلا آیا ہے کیوں نہ کہا جائے کہ اسی نے یہ بچہ بھی دیا ہے؟ مردہ سے زندہ نکالنے کے معنے مردہ سے زندہ نکالنے سے اس جگہ یہ مراد نہیں کہ حیات مردہ چیز سے پیدا ہوسکتی ہے.اس جگہ بحث بظاہر مردہ نظر آنے والی چیزوں سے زندگی کے پیدا ہوجانے کی ہے.فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ١ۚ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ١ۖۚ پس وہ اللہ (تعالیٰ)ہی (کی ہستی) ہے (جو ایسا کرتی ہے) (اور و ہی) تمہارا (حقیقی) رب (ہے )پھر حق کو چھوڑ کر فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ۰۰۳۳ گمراہی کے سوا کیا(حاصل ہو سکتا) ہے.پھر کس طرح تم (اور اور طرف) پھیرے جارہے ہو.حلّ لُغَات.ضَلَالٌ اَلضَّلَالُ اَلْھَلَاکُ ہلاکت اَلْفَضِیْحَۃُ رسوائی اَلْبَاطِلُ جھوٹ ضِدُّ الْھُدٰی گمراہی.(اقرب) علّامہ ابوحیّان بحرمحیط میں لکھتے ہیں اَلْحَقُّ وَالضَّلَالُ لَاوَاسِطَۃَ بَیْنَھُمَا.اِذْھُمَا نَقِیْضَانِ فَمَنْ یُّخْطِئُی اَلْحَقَّ وَقَعَ فِی الضَّلَالِ حق اور ضلال کے درمیان کوئی واسطہ نہیں.کیونکہ وہ ایک دوسرے کی نقیض ہیں.اس لئے جو شخص حق کو چھوڑے گا وہ ضرور باطل میں جا پڑے گا.پس بَعْدَالْحَقِّ کے معنی ہوئے ’’حق کو چھوڑ کر‘‘.تفسیر.رُبُّکُمْ الْحَقّ اور مَوْلٰھُمُ الْحَقّ کے مفہوم میں فرق اور مضمون کی ترتیب اس آیت میں رَبُّكُمُ الْحَقُّ فرمایا ہے اور آیت نمبر ۳۰ میںمَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ فرمایا تھا.کیونکہ وہاں جزاء و سزاء کا ذکر تھا اور یہاں تکمیل مدارج کا ذکر ہے.اور تکمیل مدارج کے مطابق رب کی صفت ہی ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں پیدا کرکے تکمیل تک پہنچانے والا.پس اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی طرف اشارہ کرکے بتایا گیا ہے کہ وہ خدا جو انسان کو اس طرح درجہ بدرجہ ترقی دے کر کمال تک پہنچاتا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع کو اختیار کرنا نادانی ہے.رَبُّکُمْکی صفت اَلْحَقّ لانے کی وجہ رَبُّکُمْ کی صفت الْحَقّ بیان فرماکر بتایا ہے کہ رب دو قسم کے ہوسکتے
Page 108
ہیں.ایک وہ جو ربوبیت تو کرتے ہیں مگر فانی ہوتے ہیں.ان کی ربوبیت ناقص ہوتی ہے.اور ایک ایسا رب ہوسکتا ہے جو قائم بالذات ہو اور فنا سے پاک.وہی اصل ربوبیت کرنے والا ہے.پس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف رب ہے بلکہ ازلی ابدی بھی ہے.اس لئے اس کی ربوبیت جس قدر کامل ہوسکتی ہے اور کسی وجو د کی نہیں ہوسکتی اور اسے چھوڑ کر دوسروں کو اختیار کرنا.گویا ہلاکت کی طرف جانا ہے.كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْۤا اَنَّهُمْ لَا اسی طرح جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے.ان پر تیرے رب کا فرمودہ پورا ہوا ہے.يُؤْمِنُوْنَ۰۰۳۴ کہ وہ ایمان نہیں لاتے.حلّ لُغات.کَلِمَۃٌ اَلْکَلِمَۃُاللَّفْظُۃُ لفظ کُلُّ مَا یَنْطِقُ بِہِ الْاِنْسَانُ مُفْرَدًا کَانَ اَوْمُرَکَّبًا جو کچھ بولا جائے خواہ مفرد ہو یامرکب.(اقرب) فِسْقٌ فَسَقَ الرَّجُلُ فِسْقًا تَرَکَ اَمْرَاللہِ.اللہ کی نافرمانی کی.عَصٰی نافرمان ہو گیا.جَارَعَنْ قَصْدِ السَّبِیْل.درست راہ سے روگردان ہو گیا.فَـجَرَ.بدکردار ہو گیا.خَرَجَ عَنْ طَرِیْقِ الْحَقِّ.حق کی راہ سے الگ ہو گیا.ا لرُّطَبَۃُ عَنْ قِشْرِھَا خَرَجَتْ گابھا چھلکے سے باہر آگیا.(اقرب) تفسیر.فسق انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے یعنے جس طرح یہ ثابت ہے کہ حق کے بعد سوائے گمراہی اور ہلاکت کے کچھ نہیں.اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ جو لوگ فسق کرتے ہیں یعنی اطاعت سے نکل جاتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے.اس آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے.ہدایت یا ضلالت میں بڑھنےکے متعلق ایک قانون الٰہی بلکہ اس جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ الٰہی قانون ہے کہ جو غلط راستہ پر چلے گمراہی میں ترقی کرے اور جو نیک راستہ پر چلے نیکی میں ترقی کرے اور اگر انسانی پیدائش کا کوئی مقصد ہے تو اس قانون کا ہونا بھی ضروری تھا ورنہ دنیا میں اندھیر پڑ جاتا.کہ ظلم کرنے والے اعلیٰ مدارج روحانیہ حاصل کرجاتے.اور نیک گمراہ ہوجاتے.جس شخص کے سامنے دلائل پر دلائل پیش کئے جائیں اور وہ انہیں
Page 109
تسلیم نہ کرے کس طرح جائز ہے.کہ اس کو خدا تعالیٰ زبردستی ہدایت دے دے؟نہ وہ زبردستی ہدایت دیتا ہے نہ زبردستی گمراہ کرتا ہے.ہاں اپنے دل کی حالت انسان بدل لے تو خدا تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ فوراً بدل جائے گا.قرآن کریم کیسا محبت بھرا کلام ہے !بات بات کے لئے اول تو دلائل دیتا ہے پھر ساتھ اس کے محبت بھرے جذبات کے ساتھ اپنی حالت کو بدلنے کی طرف توجہ دلاتا ہے.قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآىِٕكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ١ؕ تو (انہیں) کہہ (کہ )کیا تمہارے (قرار دادہ) شریکوں میں سے کوئی( بھی ایسا) ہے جو پہلی بار پیدا کر تا ہو( اور) قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ۰۰۳۵ پھر اس (پیدائش )کودہراتا ہو.تو( انہیں) کہہ (کہ) اللہ( تعالیٰ ہی ہے جو) پہلی بار پیدا کرتا ہے.(اور) پھر اس (پیدائش) کو دہراتا ہے.پھر تمہیں کس طرف کوپھرایا جا رہا ہے.تفسیر.خالق وہی ہے جو معید بھی ہے اس آیت میں شرک کی تردید میں ایک بہت بڑی دلیل پیش کی گئی ہے.جسے عام طور پر لوگوں نے سمجھا نہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق کا ثبوت اعادہ ہوتا ہے یعنی مخلوق کا دہرانا.ورنہ ہر شخص دعویٰ کرسکتا ہے کہ میں خالق ہوں آج اگر کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ میں نے دنیا پیدا کی ہے تو اس کا رد اس طرح ہوسکتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ پھر پیدا کرکے دکھاؤ.غرض اعادہ ہی عمل پر قدرت رکھنے کا ثبوت ہوتا ہے.پس فرماتا ہے کہ ہم صرف خلق کو پیش نہیں کرتے کہ کوئی کہہ دے کہ حضرت عیسیٰ ؑ نے یا اور کسی وجود نے بھی پیدا کیا ہے.بلکہ ہم اعادہ کو پیش کرتے ہیں.اعادہ میں دو باتیں ہوتی ہیں اول اس سے فوری طور پر امتحان ہوتا ہے.دوم اعادہ ازلی قانون کو بھی بتاتا ہے.مثلاً غلہ سے غلہ پیدا ہوتا چلا آرہا ہے.آج اگر زید خدا بن بیٹھے اور خالق ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے کہا جائے گا کہ غلہ تو اول سے پیدا ہورہا ہے اور تم اب پیدا ہوئے ہو.غرض معبودانِ باطلہ محدود زمانہ سے چلے ہیں.اور خدا تعالیٰ کے قوانین پہلے سے چل رہے ہیں.اس لئے سوال ہوسکتا ہے کہ وہ کام جو ایک مقررہ قانون کے ماتحت ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں تمہاری طرف کس طرح منسوب ہوسکتے ہیں؟ پس فرمایا کہ یہ خلق اور اعادہ کا سلسلہ کس نے بنایا ہے؟ اگر کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو بتاؤ کہ جب خدا تعالیٰ نے ازل سے پیدائش کے
Page 110
بعض قانون مقرر فرما چھوڑے تھے اور ان کے ماتحت پیدائش عالم ہورہی ہے.تو تمہارے معبودانِ باطلہ کا دخل اس میں کہاں سے ثابت ہوا اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ سلسلہ پیدائش کی دلالت سلسلہ ہدایت پر اس آیت میں ا س طرف بھی اشارہ ہے کہ جس بادشاہ نے ایک بظاہر غیرمتناہی سلسلہ مخلوق کا پیدا کیا ہے وہ اس کی ہدایت دوسروں پر کس طرح چھوڑ سکتا تھا.یا ایک زمانہ کے لوگوں کو ہدایت دے کر بعد کی نسلوں کو کس طرح محروم رکھ سکتا تھا.اگر پیدا کرنے والا اور ہوتا اور سلسلہ پیدائش کا جاری رکھنے والا اور تب تو کہہ سکتے تھے کہ پیدا کرنے والے نے ابتداء آفرینش میں ہدایت دے دی اور سلسلۂ تناسل کے جاری رکھنے والے نے پرواہ نہ کی.مگر جب پیدا کرنے والا اور سلسلہ پیدائش کو جاری رکھنے والا ایک ہی رب ہے تو بعد میں آنے والی نسلوں کو وہ ہدایت سے کس طرح محروم کرسکتا تھا؟ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآىِٕكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ١ؕ قُلِ تو (ان سے یہ بھی) کہہ (کہ )کیا تمہارے (بنائے ہوئے )شریکوں میں سے کوئی (بھی ایسا )ہے جو حق کی طرف اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ١ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ ( لوگوں کی) رہنمائی کرتا ہو (وہ تو اس سوال کاکیا جواب دیں گے) تو ہی (ان سے) کہہ( کہ) اللہ (تعالیٰ ہی ہے جو) يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى ١ۚ فَمَا لَكُمْ١۫ كَيْفَ حق کی طرف (لوگوں کی )رہنمائی کرتا ہے.پس کیا وہ (خدا) جو حق کی طرف رہنمائی کرتاہے.اس بات کا زیادہ تَحْكُمُوْنَ۰۰۳۶ مستحق ہے کہ اس (کے احکام) کی پیروی کی جائے.یا وہ (فرضی خدا )جو کہ سوائے اس (صورت) کے کہ اسے (ہدایت کا) راستہ دکھایا جائے (خود بھی) راہ نہیں پاتا.پھر تمہیں (یہ) کیا (ہو گیا) ہے ؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو.حلّ لُغات.یَـھِدِّیْ یَھِدِّیْ ھُدًی میں سے باب افتعال کا فعل مضارع ہے.اس میں’’ ت‘‘ کو ساکن کرکے ’’د ‘‘میں ادغام کیا گیا ہے.جو لفظ یَہْتَدِیْ کا دوسرا طریق تلفظ ہے.اس کی ماضی اِہْتَدٰی ہے.جس کے معنی ہیں بتائے ہوئے راستہ کو اختیار کیا.اقرب میں ہے اِھْتَدٰی اِھْتِدَاءً مُطَاوِعُ ھَدَی یعنی بتائی ہوئی ہدایت کو قبول کیا.(اقرب)
Page 111
تفسیر.معبود حقیقی وہی ہے جو ہادی حقیقی ہے یعنی اگر خدا تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا تو کیا تمہارے معبود ہدایت دیتے ہیں.اگر وہ ہدایت دیتے ہوں تو بے شک تم کہہ سکتے ہو کہ اب خدا تعالیٰ نے ہدایت کا کام ان کے سپرد کر چھوڑا ہے.مگر کیا ایک مثال بھی اس کی پیش کرسکتے ہو کہ کسی بت یا معبود باطل کی طرف سے کوئی شریعت یا ہدایت نامہ آیا ہے؟ یہ عجیب بات ہے کہ شرک تو دنیا میں بہت پھیل رہا ہے مگر ایک کتاب بھی دنیا میں موجود نہیں جسے دنیا کی ہدایت کا دعویٰ ہو اور جس کی نسبت یہ کہا گیا ہو کہ کسی بت یا کسی معبود باطل نے اسے بطور وحی کسی پر اتارا ہے.ہر قسم کے جھوٹ بنے ہیں مگر ایسی کتاب کا جھوٹا دعویٰ کسی نے نہیں کیا.پس جب جھوٹے طور پر بھی کسی بت کی طرف ہدایت منسوب نہیں تو کیا وجہ ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے آنے کا انکار کرتے ہیں؟ آخر جس نے پیدا کیا ہے ضرور ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کا کوئی سامان کرے.ساتھ ہی شرک کا بھی رد فرما دیا.کہ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى وہ جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے یا وہ جسے جب تک ہدایت نہ دی جائے خود بھی ہدایت نہیں پاسکتا.ہدایت سےمراد ہدایت سے مراد اس جگہ روحانی امور کی ہدایت بھی ہوسکتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلانا بھی اور یہ معنی بتوں پر صادق آتے ہیں کہ جن کو لوگ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتے ہیں.انبیاء بھی ہادی ہیں مَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ سے مراد میرے نزدیک انبیاء بھی ہوسکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہدایت دینے کے لئے آتے ہیں.اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء اس قابل ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے یا وہ بت یا ان کے پجاری جو خود ہدایت کے محتاج ہیں.اور نبیوں کی تعلیم کے مقابل پر کوئی ایسی تعلیم نہیں پیش کرسکتے جو ان کے معبودوں نے اتاری ہو.وَ مَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا١ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ اور ان میں سے اکثر (اپنے )وہم کے سوا (اور کسی چیز) کی پیروی نہیں کرتے (حالانکہ) وہم حق کی جگہ کچھ بھی کام الْحَقِّ شَيْـًٔا١ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ۰۰۳۷ نہیں دیتا.جو کچھ یہ (لوگ )کرتے ہیں( اسے)اللہ( تعالیٰ) یقیناً خوب جانتا ہے.حلّ لُغات.ظَنَّ اَلظَّنُّ ھُوَ الْاِعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ اِحْتِمَالِ النَّقِیْضِ.وَیُسْتَعْمَلُ فِی الْیَقِیْنِ
Page 112
وَالشَّکِّ یعنی ظن کے معنی زیادہ تر خیال غالب کے ہوتے ہیں.اور بعض وقت یقین کے معنی میں اور بعض دفعہ شک کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.وَیَکُوْنُ اِسْمًا وَمَصْدَرًا.اور یہ لفظ اسمی معنی یعنی غالب خیال یا یقین یا شک پر بھی بولا جاتا ہے.اور مصدری معنی یعنی غالب خیال رکھنے یا یقین کرنے یا شک کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے.اَغْنٰی اَغْنٰی عَنْہُ غِنَاءَ فُلَانٍ نَابَ عَنْہُ وَأَجْزَأَہُ جو فائدہ فلاں شخص سے حاصل ہونا متوقع تھا وہی فائدہ پہنچایا.اور اس کی نیابت کی.مَااَغْنٰی شَیْئًا اَیْ لَمْ یَنْفَعْ شَیْئًا فِی مُھِمٍّ وَلَمْ یَکْفِ مُؤُوْنَةً کچھ فائدہ نہ دیا.(اقرب) تفسیر.ظن کے تین معنی ہوتے ہیں.(ا) غالب گمان (۲) شک (۳) یقین.اس جگہ ظن شک کے معنوں میں آیا ہے.کیونکہ حق اور غالب گمان کبھی ٹکرایا نہیں کرتے.غالب گمان جو دلائل پر مبنی ہوتا ہے اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب حق مخفی ہو.جب حق ظاہر ہو تو پھر غالب گمان کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا.اس وقت تو صرف ظنون فاسدہ ہی حق کے مقابل پر ڈٹے رہتے ہیں.کیونکہ ان کی بنیاد دلیل پر نہیں ہوتی ضد پر یا کمزوری نفس پر ہوتی ہے.شرک کی جڑھ وہم پرستی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض اوہام کی بنا پر مشرکانہ خیالات میں مبتلا ہیں ورنہ معبودانِ باطلہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ تو آیا نہیں.اور یہ جو فرمایا کہ اکثر لوگ اوہام کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ بعض لوگ شرک کو بدلائل مانتے ہیں بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ بعض تو لالچ اور حرص سے یا ضد سے شرک میں مبتلا ہیں گو دل میں خوب جانتے ہیں کہ شرک کا عقیدہ جھوٹا ہے.لیکن اکثر لوگ واقع میں شرک کو صحیح سمجھتے ہیں.مگر ان کا یہ یقین حقیقی نہیں ہوتا.جو دلائل پر یا مشاہدہ پر مبنی ہو.بلکہ صرف اوہام پر اس کی بنیاد ہوتی ہے.اگر وہ اصولی طور پر غور کریں تو اس وہم سے چھٹ سکتے ہیں.مخالفین کی مخالفت کو حتی الوسع بد دیانتی پر محمول نہیں کرنا چاہیے اس آیت میں پھر قرآن کریم نے اس صداقت کا اظہار کیا ہے کہ اپنے مخالف لوگوں کو بددیانت اور جھوٹا نہیں کہنا چاہیے.اکثر لوگ واقع میں اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں گو اس پر یقین کی وجہ بھی ان کے نفس کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے.کیونکہ وہ سچائی کے معلوم کرنے کی پوری کوشش نہیں کرتے اور سستی سے کام لیتے ہیں.
Page 113
وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ اور اس قرآن کا اللہ( تعالیٰ) کے سواء( کسی اور) کی طرف سے جھوٹے طور پر بنا لیا جانا (ممکن ہی) نہیں ہو سکتا.تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ بلکہ یہ (تو)اس (کلام الہٰی) کی تصدیق (کرتا )ہے جو اس کے سامنے (موجود )ہے اور کتاب (الہٰی) کی تفصیل فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ۫۰۰۳۸ (بیان کرتاہے )اس میں کچھ بھی شک نہیں ہے (اور یہ) تمام جہانوں کے رب کی طرف سے (نازل شدہ) ہے.حلّ لُغَات.اَنْ حَرْفٌ یَجِیْءُ عَلٰی اَرْبَعَۃِ اَوْجُہٍ.اَحَدُھَا اَنْ تَکُوْنَ حَرْفًامَصْدَرِیًّانَاصِبًا لِلْمُضَارِعِ فَتَکُوْنَ مَعَ صِلَتِھَا عَلٰی حَسْبِ مَایَطْلُبُہَا الْعَامِلُ (اقرب) یعنی اَنْ چار طرح کا ہوتا ہے.اول یہ کہ وہ فعل سے پہلے آکر اسے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اور حسب موقعہ و محل جزو کلام بنتا ہے.ٍٍ تَصْدِیْقٌ اَلتَّصْدِیْقُ نِسْبَۃُ الصِّدْقِ بِالْقَلْبِ اَوِ اللِّسَانِ اِلَی الْقَائِلِ سچا سمجھنا سچا ظاہر کرنا.صَدَّقَہٗ ضِدُّ کَذَّ بَہٗ سچا قرار دیا.سچا بتایا.(اقرب) تفصیل فَصَّلَ الشَّیْءَ جَعَلَہٗ فُصُوْلًا مُتَـمَائِزَۃً کسی چیز یا کسی بات کے کئی حصے قرار دے کر انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کرکے دکھایا.اَلْکَلَامَ بَیَّنَہٗ و اضح اور روشن کیا.(اقرب) تفسیر.قرآن انسانی کلام نہیں ہو سکتا اس سے پہلے تو یہ مضمون بیان ہو رہا تھا کہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے کلام بھیجے اور یہ کہ اس کے سوا انسان یا معبودان باطلہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روحانی ہدایت نامہ بناسکیں.اور واقع بھی یہ ہے کہ کسی معبود باطل نے ایسا ہدایت نامہ نہیں نازل کیا.اب اصولی بحث سے سوال زیر بحث کی طرف توجہ کی ہے.اور اس مخصوص سوال کو لیا ہے کہ کیا قرآن کریم انسانی کلام ہوسکتا ہے؟ اور جواب یہ دیاہے کہ نہیں.اس آیت میں نہایت لطیف بحث قرآن کریم کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے متعلق کی ہے.مگر مجھے افسوس ہے کہ مفسرین نے اس کی خوبیوں کی طرف پوری توجہ نہیں کی اور بہت محدود روشنی اس پر ڈالی ہے.
Page 114
قرآن کریم کے مضامین کی شہادت اس کے منجانب اللہ ہونے پر گواہ ہے اس آیت میں پانچ زبردست ثبوت قرآن کریم کے منجانب اللہ ہونے کے متعلق دیئے ہیں.اول ثبوت یہ دیا ہے کہ یہ کتاب ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو بندہ اپنے طور پر معلوم ہی نہیں کرسکتا.صرف خدا تعالیٰ ہی بتاسکتا ہے.کیونکہ فرمایا کہ یہ قرآن خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر بنایا ہی نہ جاسکتا تھا.جس سے صاف اشارہ کر دیا کہ اس میں وہ مضامین ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ان امور میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک امور غیبیہ ہیں یعنی آئندہ زمانہ کی پیشگوئیاں.چنانچہ اسی سورۃ میں ہے فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ تو کہہ دے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے.پس جو کلام ایسے امور پر مشتمل ہو جسے خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیںبتا سکتا اس کے منجانب اللہ ہونے میں کیا شبہ ہوسکتا ہے؟ تعجب ہے کہ اس حصہ آیت پر ریورنڈ ویری نے بحوالہ برنکمینز نوٹس آن اسلام اپنی تفسیر میں اعتراض کیا ہے کہ یہ بے دلیل دعویٰ ہے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن خدا کے سوا کوئی نہیں بناسکتا تھا.اور یہ نہیں بتایا کہ کیوں مجھے افسوس ہے کہ ریورنڈ ویری زبان کی ان باریک خوبیوں کے علم سے بالکل محروم ہیں جن کے بغیر کوئی زبان زبان کہلانے کی مستحق ہی نہیں ہوسکتی.اور خصوصاً عربی زبان تو اس کمال میں خصوصیت رکھتی ہے کہ وہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مضمون بیان کردیتی ہے.ھٰذَا الْقُرْآنَ میں لفظ ھٰذَا کا افادہ اس آیت میںهٰذَا کا لفظ اس دعویٰ کو واضح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا تھا.بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس قرآن کو حالانکہ قرآن ایک ہی کتاب ہے دو کتابوں کا نام قرآن نہیں کہ ’’اس‘‘ کے لفظ کے لانے کی ضرورت ہوتی.’’اس‘‘ کا لفظ اس اشارہ کے لئے لایا گیا ہے کہ یہ کتاب اپنے مطالب کے لحاظ سے اس قدر بلند ہے کہ اسے کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا.اور یہ فقرہ بے دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل پر مشتمل ہے اور اس میں صاف بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں جو صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آسکتی ہیں.اور قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ باتیں کون سی ہیں.پس انہی باتوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے.ہر زبان میں اس قسم کے جملے استعمال کئے جاتے ہیں.مثلاً اردو میں بھی اس قسم کے فقرے بولے جاتے ہیں.کہ کیا یہ شخص جھوٹا ہوسکتا ہے یا کیا یہ بات غلط ہوسکتی ہے.اور کوئی عقل مند ایسا نہ ہوگا جو یہ کہے کہ یہ فقرہ بے دلیل ہے کیونکہ ایسے فقروں کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ان کی بعض مشہور عام خوبیاں جن کے خاص طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہر شخص انہیں جانتا ہے ایسی ہیں کہ انہیں مدنظر رکھتے ہوئے ممکن نہیں کہ
Page 115
وہ شخص جھوٹا ہو یا وہ بات غلط ہو.صرف ’’اس‘‘ کے لفظ سے یہ سب مضمون پیدا کرلیا جاتا ہے.غرضهٰذَا کا لفظ اس آیت کے مطلب کو بالکل واضح کر دیتا ہے.مگر بعض مسیحی مشنری بغیر عربی زبان کی باریکیوں سے واقف ہونے کے قلم اٹھا لیتے ہیں اور خود بھی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان ناواقف لوگوں کو بھی مبتلا کرتے ہیں جو ان پر اعتبار کرتے ہیں.کاش کہ وہ بعض غیرمتعصب مستشرقین سے ہی مشورہ کرلیا کرتے.کتب سابقہ کی پیشگوئیوں کی شہادت دوسری دلیل قرآن کریم کے کامل روحانی ہدایت نامہ ہونے کی یہ دی ہے کہ جس طرح اس کی اپنی پیشگوئیاں اس کے مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ ہونے کے خیال کو غلط ثابت کرتی ہیں اسی طرح پہلے انبیاء کی پیشگوئیاں بھی اس خیال کو غلط ثابت کرتی ہیں کیونکہ پہلے انبیاء کا کلام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں بھی اس کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں ہیں.اگر اسے تسلیم نہ کرو گے تو سب انبیاء کو جھوٹا قرار دینا ہوگا کیونکہ ان کی وہ پیشگوئیاں جو اس کے متعلق ہیں غلط تسلیم کرنی ہوں گی.قرآن کریم کا کتب سابقہ کی تصدیق کرنا قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ بجائے پہلوں کو پچھلوں کا مصدق قرار دینے کے پچھلوں کو پہلوں کا مصدق قرار دیتا ہے.چنانچہ حضرت مسیح حضرت یحییٰ وغیرہم انبیاء کی نسبت اسی رنگ میں اس نے ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گو پہلوں کی پیشگوئیاں پیچھے آنے والوں کی نسبت ہوتی ہیں مگر بعد میں آنے والے انبیاء ان پیشگوئیوں کو پورا کرکے پہلے انبیاء کی صداقت پر مہر لگاتے ہیں.اس حقیقت کے بیان کرنے کا بہترین طریق وہی ہے جو قرآن کریم نے اختیار کیا ہے.کیونکہ یہ کہنا کہ اس نبی کے یا اس کلام کے پہلے انبیاء مصدق ہیں اس قدر مؤثر نہیں ہوسکتا جس قدر یہ کہنا کہ اس کلام کے ذریعہ سے ہی پہلے نبی کی تصدیق ہوتی ہے.ورنہ اسے جھوٹا ماننا پڑتا ہے اس دلیل کے آگے پہلے انبیاء کے اتباع کو فوراً دبنا پڑتا ہے.کیا قرآن کریم موجودہ توریت و انجیل کو انسانی دستبرد سے پاک قرار دیتاہے ؟ مسیحی مشنریوں نے اس قسم کی آیات سے ایک انوکھا استدلال کیا ہے اور وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ان آیات سے یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم موجودہ توراۃ و انجیل کو انسانی دستبرد سے پاک قرار دیتا ہے.حالانکہ یہ کہنا کہ یہ کلام پہلے کلام کا مصدق ہے صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا.اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ اب تک محفوظ بھی ہے ایک ایسا نتیجہ ہے جو الفاظ سے زائد ہے اور زائد نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوتا.قرآن کریم توراۃ اور انجیل کی تحریف کے حوالہ جات سے بھرا ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر ایک زبردست شاہد ہے.اگر واقع میں ان آیات کا وہ مطلب ہوتا جو یہ لوگ بتاتے ہیں تو اس وقت کے مسیحی اور یہودی اس پر اعتراض کرتے لیکن ایسا اعتراض ان کی
Page 116
طرف سے بالکل ثابت نہیں ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہود کی کتب میں جو باتیں ہیں ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو.اگر ان کتب کو غیرمحرف سمجھا جاتا تو ان کی تصدیق سے کیوں روکا جاتا؟ کسی کتاب کا حوالہ دینا اس ساری کتاب کی درستی کو تسلیم کرنے کا مستلزم نہیں باقی رہا یہ کہ قرآن کریم نے ان کتب کا حوالہ دیا ہے سو یہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ کتب محرف نہیں ہیں.سب دنیا تاریخی کتب کا حوالہ دیتی ہے اور کوئی عقلمند کسی تاریخی کتاب کو شروع سے آخر تک صحیح نہیں سمجھتا.حوالہ سے مراد صرف اس خاص واقعہ کی تصدیق ہوتی ہے نہ کہ سب کتاب کی.پہلی کتب قرآن کریم کی تفصیل کی محتاج ہیں تیسری دلیل یہ دی ہے کہ قرآن کریم پہلی کتب کی تفصیل کرتا ہے.یہ بھی ایک زبردست ثبوت قرآن کریم کی صداقت کا ہے.بغیر قرآن کریم کے مضامین سے مدد لینے کے کوئی پہلی کتاب حل نہیں ہوسکتی.توراۃ، انجیل، وید ،ژند، اوستا سب کتب میں توحید، صفات باری کے ظہور، وحی، نبوت، بعدالموت، امور اخلاق، امور روحانیہ وغیرہا کے متعلق بحثیں ہیں.لیکن کوئی کتاب بھی ان امور کو واضح کرکے بیان نہیں کرتی بلکہ قرآن کریم کی مدد سے ان کو حل کرنا پڑتا ہے.مسئلہ توحید کی قرآن کریم میں تفصیل توحید سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے.اسی کو لے لو.ان سب کتب میں اس کا ذکر ہوگا مگر بالاجمال.چنانچہ قرآن کریم سے پہلے کی جو کتب توحید کے متعلق ان کتب کے پیرووں نے لکھی ہیں یا جو مضامین لکھے ہیں انہیں پڑھ کر دیکھ لو وہ توحید کے متعلق بہت ہی ناقص معلومات دیتی ہیں مگر قرآن کریم کے بعد ان کے پیرووں کی کتب کا رنگ ہی اور ہو گیا ہے.جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی مطالب کے پھیلنے سے ان لوگوں پر اصل حقیقت کھلی اور ان کی مدد سے انہوں نے اپنے مذہب کے عقائد کی تشریح کی.مسئلہ نبوت کی تفصیل نبوت کا مسئلہ ایسا اہم مسئلہ ہے لیکن توراۃ اور انجیل اور دوسری کتب اس کے متعلق اس حد تک خاموش ہیں کہ ان کے پیرو اب تک نہیں بتا سکتے کہ نبی سے مراد ان کی کتب میں کن لوگوں سے ہے؟ مگر قرآن کریم نے اس مضمون کو بھی خوب واضح کیا ہے.یہی دوسرے اہم مسائل کا حال ہے.پس اس آیۃ میں بتایا گیا ہے کہ پہلی کتب کے مطالب کی تفصیل اس کتاب سے ملتی ہے.اگر تم اس کتاب کا انکار کرو گے تو ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ وہ باتیں اپنی کتب میں بیان نہ کرسکا جو اس شخص نے ایک چھوٹی سی کتاب میں بیان کردیں.پس یا اسے سچا ماننا پڑے گا یا پہلی کتب کو بھی جھوٹا ماننا پڑے گا.
Page 117
امور غیبیہ کا پورے طور پر بیان چوتھی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے.یعنی یہ کتاب اپنے دلائل خود بیان کرتی ہے.کسی کی مدد کی محتاج نہیں.اس میں مضامین ایسے رنگ میں بیان ہوئے ہیں کہ جو شخص ان پر پورے طور پر تدبر کرے اسے ساتھ کے ساتھ دلائل ملتے جاتے ہیں اور شک اس کتاب کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ خود دلائل بیان کردیتی ہے.بلکہ شک اگر پیدا ہوتا ہے تو انسان کی اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سےاور یہ امر بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ یہ بات کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ امور غیبیہ کو پورے طور پر ثابت کرسکے کیونکہ ان میں سے کئی خالی عقلی دلیل سے ثابت نہیں ہوسکتے.بلکہ اس کے ساتھ مشاہدہ کی دلیل کے بھی محتاج ہوتے ہیں.اور امور غیبیہ کے لئے مشاہدہ کے سامان پیدا کر دینا انسان کی طاقت سے بالا ہے اور صرف خدا تعالیٰ کے لئے ممکن ہے کہ امور غیبیہ کے لئے ایسے ثبوت بہم پہنچا دے جو مشاہدہ کا رنگ رکھتے ہوں.اپنے متبعین پر الہام کا دروازہ کھولنا مثلاً الہام ایک امر غیبی ہے ایک انسان عقلی دلیلیں تو دے سکتا ہے لیکن الہام کا دروازہ کسی کے لئے نہیں کھول سکتا.نہ اس کا وعدہ کرسکتا ہے.مگر خدائی کلام یہ کرسکتاہے.وہ یہ دعویٰ بھی کرسکتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر الہام کا دروازہ کھولا جائے گا.اور اس کے اس دعویٰ کی تصدیق خدا تعالیٰ کے فعل سے بھی ہوسکتی ہے.پس جو کلام کلام الٰہی کے نازل ہونے کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کرے کہ یہ عجیب بات نہیں.اب بھی کلام الٰہی نازل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور سینکڑوں لوگ اس کے ذریعہ سے کلام الٰہی کو سنیں گے.اس کے خدائی کلام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہوسکتا.کیونکہ بندہ کی طاقت میں نہیں ہے کہ ایسے ثبوت بہم پہنچا سکے اور شک کا اس طرح قلع قمع کرسکے.اس کتاب کا تمام عالمین کے لئے ہونا اس کے منجانب اللہ ہونے پر گواہ ہے پانچویں دلیل یہ دی ہے کہ یہ کلام رب العٰلمین خدا کی طرف سے ہے.یعنی اس کی تعلیم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رب العٰلمین کی صفت ظاہر ہوئی ہے کسی قوم یا کسی زمانہ سے مخصوص نہیں جس طرح کہ پہلی کتب ہوتی تھیں.بلکہ سب اقوام اور سب زمانوں کے لئے ہے اور ہر زمانہ کی ضرورتوں اور اس کے مفاسد کا اس میں خیال رکھا گیا ہے اور یہ امر بھی کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ سب اقوام اور سب زمانوں کا خیال رکھ سکے.انسان تو اپنے گردوپیش کے حالات سے متاثر ہوتا ہے اور اپنی ان ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے جو اس کے سامنے ہوں.اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایسی تعلیم آسکتی ہے جو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے یکساں مفید ہو.اور زمانہ کے تغیرات اس پر کوئی اثر نہ ڈال سکیں.اور انسانی فطرت کے تمام
Page 118
تقاضاؤں اور تمام احساسات کا اس میں خیال رکھا گیا ہو.قرآن کریم میں یہ خوبی پائی جاتی ہے وہ یکساں طور پر تمام انسانی طبائع کا لحاظ رکھتا ہے.نہ اس میں یہ تعلیم ہے کہ تو صرف رحم ہی کئے جا اور نہ یہ کہ تو معاف ہی نہ کر.بلکہ یہ تعلیم ہے کہ تو رحم کے موقع پر رحم کر اور سزا کے موقع پر سزا دے.اسی طرح تمام تعلیمات اس کی ایسی ہیں کہ ان میں تمام طبائع اور تمام زمانوں کا لحاظ رکھا گیا ہے اور جاہل اور عالم کا خیال رکھا گیا ہے.اور یہ ایک زبردست ثبوت اس کے خدا کا کلام ہونے کا ہے.فتبارک اللہ احسن الخالقین.اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ١ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا مَنِ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس (شخص) نے اسے (اپنی طرف سے) گھڑ لیا ہے.تو (انہیں) کہہ (کہ ) اگر تم (اس بیان میں) سچے ہو اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۰۰۳۹ تو اس جیسی کوئی ایک (ہی) سورت لے آؤ.اور اللہ (تعالیٰ )کے سوا جس (کسی کو بھی بلانے )کی تمہیں طاقت ہو(اپنی مدد کے لئے) بلا لو.حلّ لُغات.سُوْرَۃٌ اَلسُّوْرَۃُ.اَلْمَنْزِلَۃُ مرتبہ اَلرِّفْعَۃُ بلندی مرتبہ.اَلْفَضْلُ.فضیلت.اَلشَّرَفُ عظمت و بزرگی.مَاطَالَ مِنَ الْبَنَاءِ اِلَی جِھَۃِ السَّمَاءِ وَحَسُنَ بلند اور خوبصورت عمارت.اَلْعَلَامَۃُ دلیل و نشان.اَلقِطْعَۃُ الْمُسْتَقِلَّۃُ.مستقل حصہ.(اقرب) تفسیر.نظیر لانے کے لئے تحدی یعنی باوجود ان خوبیوں کے جو اوپر بیان ہوئیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا افتراء ہے.اگر ان خوبیوں والا کلام افتراء ہوسکتا ہے تو پھر کیوں یہ لوگ ایسا کلام بناکر پیش نہیں کرتے.اس آیت میں قرآن کریم نے تحدی کی ہے مگر افسوس کہ مفسرین نے اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے.اور بتایا ہے کہ اس دعویٰ میں صرف زبان کو نہیں بلکہ قرآن کریم کی سب خوبیوں کو پیش کیا گیا ہے.بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس دعویٰ سے یہ مراد ہے کہ جو کوئی کلام بنا کر اس کے مقابل پر پیش کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا.اس تحدی کے بیان میں قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں میرے نزدیک جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں مفسرین نے اس مضمون کی حقیقت کو جو اس جگہ بیان ہوا ہے نہیں سمجھا.یہ مضمون مختلف الفاظ میں کئی مقام پر بیان ہوا ہے.اور لوگوں نے غلطی سے یہ خیال کیا ہے کہ مختلف زمانوں میں قرآن کریم نے اپنے دعویٰ کو بدلا ہے.
Page 119
کبھی پورے قرآن کریم کی مثال لانے کو کہا ہے.کبھی دس سورتوں کی مثال لانے کو اور کبھی ایک سورۃ کی مثال لانے کو.مگر میرے نزدیک یہ درست نہیں.اس سورۃکی تحدی میں سورۃسے مراد ایک دلیل ہے حقیقت یہ ہے کہ ان سب جگہوں پر الگ الگ مضمون بیان ہوا ہے.اور مختلف طریق پر مثال لانے کا مطالبہ کیا ہے.مثلاً اس آیت میں جو یہ دعویٰ ہے کہ فَأْتُوْا بِسُوْرَۃٍ مِّثْلِہٖ اس سے مراد سارا قرآن کریم نہیں ہے بلکہ مراد اوپر کی آیت ہے اور سورت سے مراد اس جگہ علامت ہے یعنی دلیل اور یہ پوچھا گیا ہے کہ جو دلیلیں ہم نے اوپر دی ہیں اگر یہ کلام انسانی کلام ہے تو کسی انسانی کلام میں وہ پانچوں دلیلیں جمع کرکے دکھانا تو بڑی بات ہے تم ایسا انسانی کلام ہی پیش کر دو جس میں ان میں سے ایک دلیل ہی پائی جاتی ہو.مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اوپر کی بیان کردہ دلیلوں اور صداقت کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی کسی انسانی کلام میں نہیں پائی جاسکتی.اور یہ دعویٰ قرآن کریم کا ایسا ہے کہ اس کا جواب نہ اب تک کوئی دے سکا ہے اور نہ آئندہ دے سکے گا.اب بھی یہ تحدی موجود ہے اس زمانہ میں کوئی شخص ان پانچ علامتوں والا کلام تو الگ رہا ان میں سے ایک علامت والا کلام ہی بنا کر قرآن کریم کے مقابل پیش کر دے.تو ہم قرآن کریم کے دعوے کو باطل سمجھ لیں گے.مگر زمین و آسمان ٹل جائیں کوئی شخص ایسا نہیں کرسکتا.یہ پانچوں علامتیں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے کلام میں پائی جاسکتی ہیں.کوئی بندہ ان میں خدا تعالیٰ کی نقل نہیں کر سکتا.لفظ سورۃ سے مراد پوری سورۃ لینے سے معنوں میں وسعت نہیں رہتی اگر سورۃ سے مراد سورۃ ہی لی جائے تب بھی اس سے مراد یہ ہوگی کہ جس قسم کا کلام ہم نے اوپر پیش کیا ہے ایسی کوئی سورۃ بنا کر پیش کرو.لیکن اس صورت میں معنوں میں وہ وسعت نہیں رہتی.جو اون معنوں میں ہے کیوں کہ ان معنوں میں ان مطالب کا پوری سورۃ کا مطالبہ کیا ہے اور پہلے معنوں میں مذکورہ بالا دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کا.باقی مقامات جن میں اس دعویٰ کو دوسرے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے ان کے متعلق انشاء اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں تفصیل سے بیان کیا جائے گا.وَ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ کے جملہ سے اس مضمون کو اور بھی زور دار کردیا ہے کہ خود ہی زور نہ لگاؤ بلکہ اپنے لیڈروں اور معبودان باطلہ کو بھی بلا لو اور پھر دیکھو کہ تم کیسے ناکام رہتے ہو.تا دنیا پر بھی یہ ثابت ہو جائے کہ جس کتاب کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو اسے تم اور تمہارے لیڈر اور تمہارے معبود بھی مل کر نہیں بناسکتے.
Page 120
بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَ لَمَّا يَاْتِهِمْ (مگر ان کا یہ خیال درست نہیں )بلکہ (حقیقت میں) انہوں نے (ایک) ایسی چیز کو جھٹلا دیا ہےجس کا انہوں نے پورا تَاْوِيْلُهٗ١ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ علم حاصل (ہی) نہیں کیا تھا اور نہ (ہی) ابھی اس کی حقیقت ان پر ظاہر ہوئی تھی.جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ۰۰۴۰ نے (بھی) اسی طرح جھٹلایا تھا.پھر دیکھ (کہ) ان ظالموں کا کیا انجام ہوا تھا.حلّ لُغات.تَأْوِیْلٌ اَلتَّأْوِیْلُ اَلظَّنُّ بِالْمُرَادِ.کسی کلام کے مطلب و مدعا کی نسبت ظن غالب بَیَانُ أَحَدِ مُحْتَمِلَاتِ اللَّفْظِ.کسی لفظ کے کئی احتمالی معانی میں سے کسی ایک کی تعیین کرنا.اَلْعَاقِبَۃُ انجام.اَوَّلَ الشَّیْءَ رَجَّعَہٗ.لوٹایا.اَلْکَلَامَ دَبَّـرَہٗ وَ قَدَّرَہٗ وَفَسَّرَہٗ تدبر کیا اور اس کا صحیح مطلب نکالا.اَلرُّؤْیَا عَبَّرَھَا تعبیر کی.(اقرب) تفسیر.قرآن کریم کو کفار کے افتراء قرار دینے کی وجہ یعنے یہ جو افتراء افتراء کہتے رہتے ہیں ان کی بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے.انسان جب کسی بات کو سمجھ نہیں سکتا تو اسے غلط قرار دے دیا کرتا ہے.یہ بھی جب قرآن کریم کے مطالب کو نہ پہنچ سکے اور اپنے متداول علوم اور رائج قانون کے اسے خلاف پایا تو جھٹ اس کا انکار کر بیٹھے.زمخشری کا قول ہے بَلْ سَارَعُوْا اِلَی التَّکْذِیْبِ بِالْقُرْاٰنِ فَاجَئُوْہُ فِی بَدِیْھَۃِ السَّمَاعِ قَبْلَ اَنْ یَفْھَمُوْہُ وَیَعْلَمُوْا کُنْہَ اَمْرِہٖ (بحرمحیط).یعنی انہوں نے قرآن کے جھٹلانے میں جلدی کی اور اس کے سمجھنے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے سے پہلے ہی اس کا مقابلہ شروع کر دیا.وَ لَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ.ابن عطیہ کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ ابھی انجام ظاہر نہیں ہوا اور وعید پورے نہیں ہوئے کہ پہلے ہی انہوں نے شور مچا دیا.یہ شور ان لوگوں کا نیا نہ تھا بلکہ پہلے انبیاء کے مخالفین بھی ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں.بلکہ حق کا مقابلہ کرنے والے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں.اس وقت کا انتظار نہیں کرتے جب حقیقت کے انکشاف کا وقت آئے.اور پہلے ہی
Page 121
انکار شروع کر دیتے ہیں.اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر ایک لمبے عرصہ تک انبیاء کی بعض باتوں کی حقیقت کے انکشاف کا انتظار ضروری ہے تو پھر ان پر ابتداء دعویٰ میں ایمان لانا تو درست نہ ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ یہ ذکر نہیں کہ ایسے ثبوت نبیوں کے پاس نہیں ہوتے.جن کی مدد سے انسان ابتداء ہی میں انہیں مان سکے.بلکہ یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ جو بعض صداقتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ بعض خاص امور کو اہمیت دے دیتے ہیں.ان کا کم سے کم فرض یہ ہے کہ وہ اس وقت تک تکذیب تو نہ کریں اگر وہ ثابت شدہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کا یہ حق بھی تو نہیں کہ جن امور کے متعلق انہیں شبہ ہے ان کی حقیقت کے اظہار سے پہلے ان پر اعتراض شروع کر دیں.كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ بعض پہلے لوگ بھی نبیوں سے اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں.یونہی شور مچا دیتے تھے.ریورنڈ ویری صاحب نے بحوالہ مسٹر برنکمین اعتراض کیا ہے کہ جب اہل مکہ کو پورا علم نہیں ہوا تھا اور انہوں نے شور مچا دیا تھا تو پھر ان کا کیا قصور تھا مگر ویری صاحب نے یہ نہیں سمجھا کہ پورا علم حاصل نہ ہونا اور بات ہے اور نہ ہوسکنا اور بات ہے.قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ انہیں پورا علم حاصل نہیں ہوسکتا تھا.بلکہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پورا علم حاصل نہ کیا تھا.اور جب انہوں نے پیش کردہ باتوں پر غور ہی نہیں کیا اور صرف رَجُلٌ مِّنْہُمْ کہہ کر انکار کر دیا تو وہ الزام سے کیونکر بری ہوسکتے تھے؟ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَ مِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ١ؕ وَ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے.اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَؒ۰۰۴۱ لائیں گے اور تیرا رب فساد کرنے والو ںکو خوب جانتا ہے.تفسیر.یعنی باوجود ان لوگوں کی اس حالت کے یہ سب لوگ ہدایت سے محروم نہیں رہیں گے.بلکہ بعض لوگ اپنی حالت کو بدل کر ایمان لائیں گے اور صرف وہ لوگ ہدایت سے محروم رہیں گے جو آخر تک فساد پر مصر رہیں گے.گویا بتایا کہ ڈھیل کی وجہ موجود ہے اور وہ یہ کہ صرف عقلی امکان ہی نہیں ہے کہ کفار مکہ میں سے بعض لوگ ڈھیل
Page 122
پاکر ایمان لا سکتے ہیں.بلکہ ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے کہ فی الواقع بھی ان منکروں میں سے بعض لوگ ایمان لے آئیں گے.اس وجہ سے ہم فوراً عذاب نہیں دیتے بلکہ ڈھیل دے رہے ہیں.یہ کیسی زبردست پیشگوئی ہے جو اپنے وقت پر پوری ہوئی.اگر اہل مکہ شروع مخالفت میں ہی تبہ کر دیئے جاتے تو خالد بن ولید ،عمرو بن عاص ،عکرمہ اور اور ایسے ہی جلیل القدر بطل اسلام کہاں سے پیدا ہوتے.وَ اِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ١ۚ اَنْتُمْ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو (انہیں) کہہ (کہ) میرا کِیا( خو د) میرے لئے (مفید یا مضر) ہوگا اور تمہارا کیا تمہارے بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّاۤ اَعْمَلُ وَ اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ۰۰۴۲ لئے.جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری (الذمہ) ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری( الذمہ) ہوں.حلّ لُغات.بُرَآءُ بَرِیَٔ مِنْہُ.یَبْرَءُ بَرَاءَ ۃً تَخَلَّصَ وَسَلِمَ مِنْہُ بچ گیا.بے تعلق رہا.محفوظ رہا.بَرِیَٔ مِنَ الْمَرَضِ بَرْءًا بِالضَّمِّ وَاَھْلُ الْحِجَازِ یَقُوْلُوْنَ بَرَأْتُ مِنَ الْمَرَضِ بَرْءًا بِالْفَتْحِ نَقِھْتُ وَ تَعَافَیْتُ وَ شُفِیْتُ.میںصحت یاب ہو گیا.(اقرب) تفسیر.لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ فرمایا کہ اگر تم میری تکذیب کرتے ہو اور مجھے جھٹلاتے ہو تو بے شک ایسا کرو کیونکہ تم میں اور مجھ میں اختلاف ہے.تم اور کام کررہے ہو اور میں اور کام کررہا ہوں.اور اختلاف کی صورت میں ہر فریق کو حق ہے کہ دوسرے کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے.لیکن بات اسی حد تک ہی رہنی چاہیے.ایک دوسرے کو اس کی مرضی کے خلاف اپنی بات منوانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے.چنانچہ جب میں تمہیں مجبور نہیں کرتا تو تم مجھے کیوں مجبور کرتے ہو.پہلی آیت میں جو اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ کہا تھا اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب تمہاری جماعت الگ اور ہماری جماعت الگ.تمہارے کام علیحدہ اور ہمارے کام جدا.اور ہر ایک اس بات کو جانتا ہے تو پھر فساد اور جبر تک نوبت کیوں پہنچائی جائے؟ کیونکہ جبر تو اس صورت میں ہوسکتا ہے جبکہ ایک کی وجہ سے دوسرے پر حرف آتا ہو.لیکن اس جگہ میرے یا میری جماعت کے کاموں کی وجہ سے تم پر کوئی حرف نہیں آسکتا.اور تمہارے کاموں کی وجہ سے مجھ پر کوئی حرف نہیں آسکتا.پس جبر ناجائز ہے.
Page 123
اس جگہ سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ اپنی قوم کے آدمی پر ایک حد تک جبر کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے قوم بدنام ہوتی ہے.چنانچہ اس کے ماتحت جب ہم اپنی جماعت کے بعض لوگوں کی غلطی پر جرمانہ وغیرہ کی سزا مقرر کرتے ہیں تو بعض نادان اسے پیرپرستی قرار دیتے اور شور مچاتے ہیں.حالانکہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اپنی جماعت کے لوگوں پر ایک حد تک جبر ہوسکتا ہے.مثلاً اگر کوئی شخص احمدی کہلاتا ہوا ڈاکہ زنی کی وارداتیں کرتا ہے یا نمازیں چھوڑ بیٹھتا ہے تو چونکہ اس سے ساری جماعت کی بدنامی ہوتی ہے اس لئے ہمارا حق ہے کہ اس شخص کو اصلاح کے لئے مجبور کریں.ہاں اگر وہ احمدیت سے ہی انکار کرکے جدا ہوجائے یا اپنا کوئی نیا فرقہ بنالے تو پھر ہمارا اس پر کوئی حق نہ ہوگا.غرض اَنْتُمْ بَرِيْٓـُٔوْنَ مِمَّاۤ اَعْمَلُ میں بتایا ہے کہ میرے اور تمہارے الگ الگ گروہ ہیں.میرے کاموں کی وجہ سے تم پر الزام نہیں آئے گا اس لئے جبر یا فساد کی کوئی وجہ نہیں ہے.اس آیت کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ میرے اور تمہارے عمل بالکل ممتاز ہیں.ان میں کوئی تشابہ نہیں ہے.نتیجہ خود بتادے گا کہ کس کے عمل صحیح اور خدا کے ہاں مقبول تھے.عمل کے متشابہ ہونے کی صورت میں صحیح طور سے نہیں کہہ سکتے کہ خرابی یا ترقی کس سبب سے پیدا ہوئی.لیکن جب کوئی تشابہ ہی نہ ہو تو فوراً پتہ لگ سکتا ہے کہ نتیجہ اس قوم کے مخصوص اعمال کا ہے.وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ١ؕ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَ اور ان (لوگوں) میں سے (بعض ایسے) ہیں جو تیری( باتوں کی) طرف (ہر وقت) کان رکھتے ہیں.(تو) پھر کیا لَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ۰۰۴۳ تو ایسےبہروں کو اگرچہ وہ عقل سے کام (ہی )نہ لیتے ہوں (اپنی بات )سنوا لے گا.حلّ لُغات.صُمٌّ صُمٌّ اَصَمُّ کی جمع ہے صَمَّ الرَّجُلُ صَمًّا وَصَمَمًا اِنْسَدَّتْ اُذُنُہٗ وَثَقُلَ سَمْعُہٗ فَھُوَ اَصَمُّ بہرہ اَلْاَصَمُّ اَیْضًا اَلرُّجُلُ لَایُطْمَعُ فِیْہِ وَلَا یُرَدُّ عَنْ ھَوَاہُ.ایسا شخص جس کے راہ راست پر آنے کی امید نہ کی جاسکے.اور نہ اسے ہواپرستی سے روکا جاسکے.(اقرب) تفسیر.مخالفین کے انکار کی حقیقت ا س آیت اور اگلی آیت میں مخالفین اسلام کے انکار کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے.کہ ان کا انکار کسی دلیل یا معقول بات پر مبنی نہیں ہے.صرف ضد کی وجہ سے ہے وہ بظاہر تیری
Page 124
باتیں سنتے ہیں مگر درحقیقت ان کی تمام توجہ اعتراض پیدا کرنے کی طرف ہوتی ہے.نیز فرمایا کہ بہرہ اگر عقلمند ہو تو اسے بھی اشارہ سے سمجھایا جاسکتا ہے مگر ان کی حالت تو بے وقوف بہرہ کی سی ہے جو اشارے بھی نہیں سمجھتا.وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ١ؕ اَفَاَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ لَوْ اور ان میں سے بعض ایسے( بھی) ہیں جو تیری طرف( نظریں گاڑ کر)دیکھتے (رہتے) ہیں (تو) کیا پھر تو ان كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ۰۰۴۴ اندھوں کی اگرچہ وہ بصیرت (بھی )نہ رکھتے ہوں راہنمائی کر لے گا.حلّ لُغَات.عُمْیٌ عُمْیٌ اَعْمٰی کی جمع ہے.اس کا فعل عَمِیَ ہے.عَمِیَ ذَھَبَ بَصَرُہٗ کُلُّہٗ مِنْ عَیْنَیْہِ کِلْتَیْھِمَا بکلی آنکھوں سے اندھا ہو گیا.فُلَانٌ ذَھَبَ بَصَرُ قَلْبِہٖ وَجَھِلَ دل کا اندھا اور بصیرت سے کورا ہو گیا.غَوٰی بدراہ ہو گیا.(اقرب) تفسیر.ترجمہ والے عام طور پر یہاں غلطی کرجاتے ہیں اورلَا يُبْصِرُوْنَ کے معنی ’’نہیں دیکھتے‘‘ کر دیتے ہیں.حالانکہ جب انہیں پہلے اندھا قرار دیا جاچکا تو پھر لَا يُبْصِرُوْنَ کے معنی نہ دیکھنے والے کرنا کیونکر درست ہوسکتے ہیں.بلکہ جس طرح سے کہ پہلے انہیں بہرے قرار دے کر عقل کی نفی کی تھی ایسا ہی یہاں پر انہیں اندھے بتا کر بصارت کی نہیں بلکہ بصیرت کی نفی کی ہے.کیونکہ اندھے ہونے کے باوجود بھی اگر ان میں بصیرت ہو تو وہ ہدایت حاصل کرسکتے ہیں.محض ظاہر پر نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کرناچاہیے اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محض ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے.ظاہر پر نظر رکھنے والا بعض اوقات کہہ اٹھتا ہے کہ یہ کافر ہیں.ان پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ حالانکہ ان دشمنوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں اور ان کے ہدایت پانے کی امید کی جاسکتی ہے.اور دوسری طرف بعض آدمی ماننے والے خیال کئے جاسکتے ہیں.لیکن حقیقت میں وہ ایسے ہیں جو سنتے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے.بلکہ ان کی نظر ہمیشہ اعتراض کی طرف رہتی ہے.نہ ان میں عقل ہے نہ بصیرت اسی وجہ سے عذاب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.دوسرا شخص ظاہر سے دھوکا کھانے کی وجہ سے اس کو غلط طور پر وارد کرسکتا ہے.ان معنوں کے رو سے یہ آیتیں وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ(یونس :۴۱) کی تفسیر ہیں.یعنی انسان ظاہر پر نظر ڈال کر غلطی کرسکتا ہے مگر خدا تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے.
Page 125
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْـًٔا وَّ لٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ اللہ( تعالیٰ کی شان) یقیناً( ایسی ہے کہ وہ) لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا.بلکہ لوگ اپنی جانوں پر يَظْلِمُوْنَ۰۰۴۵ ( آپ ہی) ظلم کرتے ہیں.تفسیر.اس آیت میں کیا ہی لطیف بات بیان فرمائی ہے جس طرح ٹیپ کا مصرعہ دل پر پڑتا ہے اسی طرح یہ آیت ہے.فرمایا ہم جنہوں نے نبی بھیجا ہم تو منکروں کو ڈھیل دے رہے ہیں.اور نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جلد ہلاک ہوں.لیکن یہ لوگ عذاب کی جلدی کرتے ہیں.ہم نہیں چاہتے کہ ان پر ظلم ہو یعنی ان کے لئے حصول ہدایت کا ابھی موقع باقی ہو.اور عذاب آجائے مگر یہ لوگ قولاً یا عملاً عذاب کے لئے شور مچاتے ہیں.اس آیت میں ان تمام آیتوں کا جواب دے دیا گیا ہے جن سے لوگ یہ نکالا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہی بندوں کے دلوں پر مہر کردی ہے یا تقدیر کے مسئلہ کے ماتحت کہہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہی چور اور ڈاکو بنادیئے ہیں.کیونکہ یہ تمام باتیں ظلم پر مبنی اور ہدایت سے دور لے جانے والی ہیں مگر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرتا بلکہ ہدایت پانے کے لئے جس قدر ممکن ہوسکے موقع دیتا ہے.وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ اور جس دن وہ انہیں ایسی حالت میں جمع کرے گاکہ( وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ) گویا وہ دن کی ایک ساعت کے النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ١ؕ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا سوا (دنیا میں) نہیں رہے تھے( اس دن) وہ ایک دوسرے (کی حالت) کو معلوم کر لیں گے (یاد رکھو کہ) جن لوگوں نے بِلِقَآءِ اللّٰهِ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ۰۰۴۶ اللہ (تعالیٰ) کےحضور پیش ہونے( کےوعدہ) کو جھٹلایا اور وہ ہدایت کو قبول کرنے والے نہیں بنے.انہوں نے نقصان (ہی )اٹھایا.حلّ لُغَات.سَاعَۃٌ السَّاعَۃُ سِتُّوْنَ دَقِیْقَۃً.ایک گھنٹہ یا ساٹھ منٹ.اَلْوَقْتُ الْحَاضِرُ.اسی وقت.عِبَارَۃٌ مِّنْ جُزْءٍ قَلِیْلٍ مِّنَ النَّھَارِ اَوِ اللَّیْلِ.دن یا رات کا کچھ تھوڑا سا حصہ.
Page 126
تَعَارُفٌ یَتَعَارَفُوْنَ عَرَفَ میں سے باب تفاعل کا فعل مضارع ہے.تَعَارَفَ الْقَوْمُ عَرَفَ بَعْضُہُمْ بَعْضًا.ایک دوسرے کو پہچانا.ایک دوسرے کے متعلق آگاہی حاصل کی.(اقرب) تفسیر.كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ میں یہ فرمایا کہ اگر وہ خوف سے ماننے والے ہوتے تو بھی لقاء کی یاد سے ڈر جاتے.اور اگر محبت سے ماننے والے ہوتے تو بھی وہ اس میں ترقی کرتے اور ان کی اطاعت پہلے سے زیادہ ہوتی.گھڑی سے مراد سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ کے معنوں میں لوگوں کو بڑی غلطی لگی ہے.اس کے معنی دن کی ایک گھڑی کرکے پھر وہ اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ کون سی گھڑی اور کتنی بڑی گھڑی.اور پھر تطبیق دینے کے لئے انہیں اور بھی مشکل پیش آئی ہے.قرآن شریف میں متعدد جگہ کفار کے دنیا میں ٹھہرنے کو سَاعَۃً مِّنَ النَّہَارِ ہی سے تعبیر کیا گیا ہے.لیکن ان تمام جگہوں میں ان کے ٹھہرنے کا وقت بتانا مراد نہیں.بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کی زندگی خواب غفلت میں ہی گذری ہے.جس کی یہ وجہ ہے کہ نہار یعنی دن کا وقت کام کرنے کا ہوتا ہے اور کفار چونکہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ دنیا کمانے میں ہی گذارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے سے بالکل غافل رہتے ہیں اس لئے ان کے متعلق یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ وہ دن کا نہایت ہی قلیل حصہ دنیا میں رہے ہیں.خواہ بظاہر وہ لاکھوں برس ہی دنیا میں کیوں نہ رہے ہوں کیونکہ اس وقت سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا.اور جس کام کے لئے وہ دنیا میں آئے تھے اس کے لئے انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا.اس لئے ان کے دن بھی راتیں ہی ہو گئے اور وہ گویا دن کی ایک گھڑی بھر ہی دنیا میں رہے ہیں.پس ان الفاظ میں لمبے عرصہ تک ٹھہرنے کا رد نہیں بلکہ ان کے کام کے زمانہ کو چھوٹا کرکے بتانا مقصود ہے.اگر مقدار بتانا مدنظر ہوتا تو نہار کی کوئی خصوصیت نہ تھی.رات سے بھی وقت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے.غرض یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں تو ان کی آنکھوں پر پردے چھائے ہوئے ہیں لیکن قیامت کو ان پر پورا انکشاف ہو جائے گا کہ وہ نکمے پڑے رہے اور سوئے رہے اور کوئی کام نہیں کیا.يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ یعنی وہ ایک دوسرے کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے.اس دنیا میں تو لوگ باوجود آپس کے سخت اختلاف کے انبیاء کے مقابلہ میں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی مخالفت میں بڑا حصہ لینے لگتے ہیں اور انہیں برا بھلا کہنا شروع کردیتے ہیں لیکن قیامت کے دن ان سب پر حقیقت آشکار ہو جائے گی اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو دھوکا دیتے رہے ہیں وہ اس دن پھوٹ ، تفرقہ اور فضیحت کو محسوس کریں گے.مفسرین نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ آپس میں پہچان لیں گے.یعنی بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو شناخت
Page 127
کرلے گا مگر اس مضمون کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی.اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا.معرفت کے معنی صرف ظاہری صورت کو پہچان لینے کے نہیں ہوتے بلکہ حقیقت کے جان لینے کے بھی ہوتے ہیں اور یہی اس جگہ مراد ہیں.ہمارے ملک میں بھی کہا کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے یعنی آپ کی حقیقت جان لی ہے.اسی طرح قیامت کو یا جب خدائی فیصلہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبیوں کی خیرخواہی کیسی تھی.اور ان کی کیا قدر تھی اور ان کے دوستوں کی حالت اور قیمت کیا تھی! تکذ یب لقاء الٰہی کے بد نتائج كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ میں یہ بتایا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تکذیب کا نتیجہ ہے.مسلمانوں نے بھی آج اس بات کو چھوڑ دیا ہے.اس لئے وہ گررہے ہیں.اگر انسان کو یہ مدنظر رہے کہ خدا مل سکتا ہے تو خوف رکھنے والی طبیعت میں ڈر پیدا ہوجاتا ہے اور محبت رکھنے والا دل اپنے محبوب سے ملنے کی امید میں تڑپ جاتا ہے.پس یہ ایک زبردست قوت محرکہ یا موٹو پاور ہے یہی جاتی رہے تو نتیجہ بجز غفلت کے اور کیا ہوسکتا ہے.وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۠ فَاِلَيْنَا اور جس (عذاب کے بھیجنے) کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہم اس کا کوئی حصہ( تیرے سامنے بھیج کر) تجھے دکھادیں( تو مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ۰۰۴۷ توبھی دیکھ لے گا) اور( اگر) ہم (اس گھڑی سے پہلے) تجھے وفات دے دیں تو (تجھے ما بعد الموت اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کیونکہ بہرحال) انہیں ہماری طرف لوٹنا ہےپھر (یہ بات بھی تو ہے کہ )جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے.حلّ لُغَات.اِمَّا اِمَّااصل میں اِنْ مَا ہے.مَا زائدہ ہے.زائدہ ایک اصطلاح ہے.جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ حرف یا لفظ پہلے لفظ یا حرف کے معنوں کی تاکید کرتا اور ان میں قوت اور زیادتی پیدا کرتا ہے.اور اس کے بڑھنے سے کلام کے اندر ایک نئی خاصیت پیدا ہوجاتی ہے.جو اس کے اصل مفہوم کو زیادہ زوردار بنادیتی ہے.اِنْ کے ساتھ مَا کے بڑھنے سے اس کے معنی میں جو زیادتی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکیلا اِنْ تو محض ایک احتمال کا اظہار کرتا ہے.(خواہ وہ واقعی ہو یا خود پیدا کردہ) جس کے ساتھ توقع کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا اور اِمَّا ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں توقع بھی ہو.یعنی لفظ مَا لفظ اِنْ کے ظاہر کردہ احتمال کو زوردار بناکر اس کے
Page 128
متعلق توقع کا اظہار بھی کرتا ہے.تَوَفّٰی نَتَوَفَّیَنَباب تفعّل سے فعل مضارع ہے جس کاماخذ وَفَاۃٌ ہے.چنانچہ کلیات ابی البقاء میں لفظ تَوَفّٰی کے ذیل میں ہے وَالْفِعْلُ مِنَ الْوَفَاۃِ اور وفات کے معنی موت کے ہیں.(اقرب) تَوَفّٰی اللہُ زَیْدًا قَبَضَ رُوْحَہٗ.اس کی جان نکال لی.اسے وفات دے دی.اس کی روح کو قبض کرلیا.تُوُفِّیَ فُلَانٌ مَجْہُوْلًا قُبِضَتْ رُوْحُہٗ وَمَاتَ.اس کی جان نکال لی گئی اور وہ مر گیا.فَاللہُ المُتَوَفِّی وَالْعَبْدُ الْمُتَوَفّٰی.غرض ان معنوں میں اس کے استعمال کے وقت اس کا فاعل اللہ اور مفعول بندہ ہوتا ہے.(اقرب) تفسیر.اِمَّا نُرِيَنَّكَ کے معنی عام طور پر عربی سے ناواقف لوگ اس آیۃ کا ترجمہ کرنے میں غلطی کرجاتے ہیں.اصل میں یہ دو الگ الگ جملے ہیں.وَ اِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ تک ایک جملہ اور اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۠ دوسرا جملہ.پہلے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم دکھادیں تجھے بعض ان میں سے جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں.یعنی وہ غیب کی خبریں جو ہم نے ان کے متعلق تجھے بتائی ہیں.ان کا بعض حصہ تیری زندگی میں پورا کر دیں تو تو ان کو دیکھ لے گا.نَعِدُمیں وعیدی کی پیشگوئیاں اس جگہ پر تَرٰھَا محذوف ہے.اور اس جملہ میں وعیدی پیشگوئیاں مراد ہیں.جیسا کہ ان کے الفاظ سے ظاہر ہے کیونکہ کافروں سے خدا تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ نہیں کیا تھا.اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وعدہ کا لفظ وعدہ اور وعید دونوں کے لئے استعمال ہوجاتا ہے لیکن وعید کا لفظ عذاب کی پیشگوئی کے لئے خاص ہے.اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۠یا ہم تجھے وفات دے دیں.اور وہ وعید تجھے نہ دکھائیں.تو تجھ پر آخرت میں ہم ان کی حقیقت ظاہر کر دیں گے.اس جگہ پر فَنُرِیَکَ ھٰذِہٖ فِی الْاٰخِرَۃِ محذوف ہے یعنی اس صورت میں ہم ان پیشگوئیوں کا انجام تجھے آخرت میں دکھا دیں گے.عربی قاعدہ کے رو سے ایسے مواقع پر حذف بالاتفاق جائز ہے.باقی رہا یہ سوال کہ کیونکر معلوم ہوا کہ یہی الفاظ محذوف ہیں.سو یہ بات اگلے فقرہ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْسے ظاہر ہے ان الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ اس تبدیلی سے کوئی نقصان نہ ہوگا.کیونکر آخر یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی حقیقت کو وہاں ان پر ظاہر کر دے گا.اس آیت میں کفار کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم لوگ تو عذاب کے متعلق جلدی کرتے رہتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ وہ نہ صرف عذاب کے لانے میں دیر کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ وہ عذاب کی خبروں کو ٹلا
Page 129
بھی دیتا ہے.یہ آیت وعیدی پیشگوئیاں کے ٹل جانے کے ثبوت میں بنیاد کے طور پر ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام وعیدی پیشگوئیوں کے ٹلنے کے ثبوت میں اس آیت کو سب سے مقدم رکھا کرتے تھے.اور باقی آیات کو اس کی تائید میں پیش کیا کرتے تھے.اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں.(۱) یہ کہ پیشگوئیاں شرطی بھی ہوتی ہیں.کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ہم ایسا کریں گے یا ایسا (۲) یہ کہ بعض پیشگوئیاں ٹل بھی جاتی ہیں کیونکہ فرماتا ہے کہ اگر بعض ہم تجھ کو دکھلائیں گے تو تو دیکھ لے گا.بعض کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ اس جگہ ان پیشگوئیوں کا ذکر ہے جن کے پورا ہونے کا وقت آپ کی زندگی میں رکھا گیا تھا.کیونکہ جن پیشگوئیوں کا وقت آپ کی وفات کے بعد تھا وہ تو آپ کے زمانہ میں پوری ہی نہ ہونی تھیں.اس سے یہ امکان نکلتا ہے کہ کوئی بھی عذاب کی پیشگوئی تیرے وقت میں پوری نہ ہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور عذاب کی ضرورت ہی نہ رہے.یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے ورنہ سارے لوگ مانا نہیں کرتے.علاوہ ازیں اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیشگوئیوں کے لئے کوئی خاص وقت مقرر کرنا شرط نہیں کیونکہ اس جگہ وقت بہت وسیع ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک چلا گیا ہے.یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے کہ ٹلنے والی پیشگوئی وہ ہوتی ہے جو جزئی ہو.اصولی پیشگوئی نہیں ٹلا کرتی.مثلاً کوئی ہم سے کہے کہ کَتَبَ اللّٰہُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیْ (المجادلة:۲۲) والی پیشگوئی ٹل جائے گی تو ہم کہیں گے کہ نہیںکیونکہ قرآن کریم نے نَعِدُھُمْ کی شرط لگائی ہے یعنی جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں پس اس سے مراد صرف وہی وعید ہوسکتا ہے جو کسی خاص نبی کی قوم سے کیا گیا ہو.نہ وہ جو سب رسولوں کے ساتھ مجموعی طور پر ہو.اور لَاَغْلِبَنَّ والے وعدہ میں سب انبیاء شریک ہیں کسی خاص نبی سے یہ وعدہ مخصوص نہیں ہے.غرض تفصیلی پیشگوئی ٹل سکتی ہے اصولی وعدے یا وعید نہیں ٹلا کرتے.اس آیت سے آج کل کے بعض نئے مدعیوں کی تردید ہوجاتی ہے.جو پیشگوئی کرتے ہیں کہ ہم غالب آئیں گے.لیکن جب غلبہ نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ پیش گوئی ٹل گئی ہے.
Page 130
وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ١ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ اور ہر ایک قوم کے لئے ایک (نہ ایک) رسول (کا آ نا ضروری ہوتا)ہے پس جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۰۰۴۸ درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر( کوئی) ظلم نہیں کیا جاتا.حلّ لُغات.اُمَّۃٌ اُمَّۃٌکے کئی معنی ہیں.اَلْجَمَاعَۃُ.جماعت.اَلْجِیْلُ مِنْ کُلِّ حَیٍّ قبیلہ کا بڑا حصہ.الطَّرِیْقَۃُ.طریقہ.اَلدِّیْنُ مذہب.اَلْحِیْنُ وقت.جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَ لَىِٕنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ.(ہود: ۹) اَلْقَامَۃُ قد (اقرب) گویا یہ لفظ زمان و مکان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے.تفسیر.ضروری نہیں کہ ایک امت میں ایک ہی رسول آئے اس زمانہ کے بعض بدعتیوں نے اس آیت کے عجیب معنی کئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ہر امت کے لئے ایک ہی رسول ہوا کرتا ہے اس لئے امت محمدیہ میں کوئی دوسرا رسول نہیں آسکتا.یہ بات بالبداہت باطل ہے.اس آیت میں رسول کے وجود پر زور دیا گیا ہے نہ کہ تعداد پر یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ امت بغیر رسول کے نہیں ہوسکتی نہ یہ کہ امت میں ایک ہی رسول آتا ہے.اور یہ بات واقعات کے بھی خلاف ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت ہارون بھی رسول تھے اور دونوں کے مخاطب ایک تھے.اس آیت کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہر مذہبی جماعت کی ابتداء رسول کے ذریعہ سے ہوتی ہے.میرے نزدیک چونکہ اس میں ابتداءٍ امۃ کا ذکر ہے اس لئے رسول سے مراد صاحب شریعت نبی ہے.کیونکہ امت کی ابتداء شرعی رسولوںکے ہاتھوں ہی سے کی جاتی ہے.قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ یعنی جو انبیاء کی جماعت میں شامل ہونے کے قابل ہوتا ہے وہ شامل کر لیا جاتا ہے.اور جو اپنے آپ کو اس قابل نہیں بناتا وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے.اس آیت میں کفار کو یہ بتایا گیا کہ کوئی قوم خدا کے فضلوں اور اس کی برکتوں کی وارث نہیں ہوتی جب تک کہ رسول کے ساتھ وابستگی و تعلق پیدا نہ کرے.یہ امید نہ رکھو کہ تم یونہی ترقی کر جاؤ گے.اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس رسول سے سچی وابستگی اور پکا تعلق پیدا کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے.
Page 131
وَ يَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۰۰۴۹ اور وہ کہتے ہیں( کہ) اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب (پورا) ہو گا.تفسیر.مخالفین انبیاء ہمیشہ عذاب پر زور دیتے ہیں ضدی آدمی کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے.پچھلی آیت میں ضمناً یہ ذکر تھا کہ نبی سے جدا ہونا ہلاکت کا موجب ہوتا ہے.مگر باوجود اس کے کہ عذاب کی شرائط اور اس میں ڈھیل پڑنے کی وجوہ تفصیل سے پہلے بیان ہوچکی تھیں وہ اس ضمنی ذکر پر سب پہلی باتیں بھول جاتے ہیں.اور جھٹ سوال کر دیتے ہیں کہ اچھا وہ عذاب کب آئے گا؟ وہ سوائے تباہی کے نشان کے اور کسی نشان پر تشفی نہیں پاتے.افسوس کہ آج کل مسلمانوں کا بھی یہی حال ہورہا ہے.وہ صداقت کے نشانات کے طورپر ہمیشہ عذاب طلب کرتے ہیں.قُلْ لَّاۤ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ١ؕ تو (انہیں )کہہ( کہ) میں( تو) اللہ( تعالیٰ) کی مشیت کے سوا( خود) اپنے حق میں (بھی) نہ کسی نقصان پر قابو رکھتا لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ١ؕ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ۠ ہوں اورنہ کسی نفع پر.(ہاں یہ درست ہے کہ) ہر ایک قوم (کے مستوجب عذاب قرار پانے) کے لئے ایک میعاد مقرر سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ۠۰۰۵۰ ہوتی ہے (اور) جب وہ آجاتی ہے تو (اس وقت) وہ نہ کوئی گھڑی (اس سے) پیچھے رہ( کر اس سے بچ )سکتے ہیں اورنہ (ہی) آگے بڑھ( کر اس سے خلاصی پا )سکتے ہیں.تفسیر.جب میں اپنے نفع و نقصان کا بھی خودمالک نہیںتو تم پر کیوں کر کوئی عذاب لا سکتا ہوں اوپر کی آیت میں جو مطالبہ تھا اس کا ایک اور لطیف طریق پر جواب دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے ضرر اور نفع کا بھی مالک نہیں.میں تمہارے اس عذاب کے مطالبہ کو کس طرح پورا کرسکتا ہوں.توحید کا اثبات اور اس کی اہمیت و عظمت یہ آیت اور اس قسم کی دوسری آیات کس وضاحت سے ثابت
Page 132
کرتی ہیں کہ قرآن کریم کی غرض صرف توحید کا اثبات ہے وہ کسی انسان کو خدا تعالیٰ کے برابر کھڑا نہیں کرتا.خواہ وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں.اس جگہ امت سے مراد لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ سے کفر کی امۃ مراد ہے.لِکُلِّ اُمَّۃٍ رَسُوْلٌ والی امۃ مراد نہیں.اور مطلب اس کا یہ ہے کہ کفر کی جماعتوں پر ایک زمانہ ضرور ایسا آتا ہے کہ ان کا سلسلہ بند کرکے نبی کے ذریعہ سے ایک نیا سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے.یعنی گو میرے اختیار میں عذاب دینا نہیں لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر ایک قوم ایک خاص مدت تک ترقی کرتی ہے اور جب وہ اپنی حالت کو بدل لیتی ہے تو تباہ کر دی جاتی ہے.اس لئے میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس حالت پر قائم نہیں رہ سکتے.ضرور ہے کہ تم کو تباہ کرکے صداقت کا دور شروع کر دیا جائے.قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّا ذَا تو (انہیں) کہہ (کہ بھلا) بتاؤ (تو سہی کہ) اگر اس کا عذاب رات کو دفعۃً یا دن کو( تمہارے دیکھتے دیکھتے )تم پر آجائے يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ۰۰۵۱ تو مجرم لوگ اس سے کیونکر بھاگ سکیں گے.حلّ لُغَات.اَرَأَ یْتُمْ کے لفظی معنی ہیں کیا تم نے دیکھا.لیکن عربی محاورہ میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اَخْبِرُوْنِیْ مجھے بتاؤ تو سہی.(اقرب) بَیَاتٌ اَلْبَیَاتُ اِسْمٌ مِنْ بَیَّتَ الْعَدُوِّ کَا لْکَلَامِ مِنْ کَلَّمَ.بَیَاتٌ کے معنی تَبْیِیْتٌ کے ہیں.جو بَیَّتَ کی مصدر ہے.بَیَّتَ الْاَمْرَ عَمِلَہٗ اَوْ دَبَّـرَہٗ لَیْلًا.بَیَّتَ کے معنی ہیں رات کو کام کیا.یا رات کو اس کی تدبیر کی.اَلْقَوْمَ وَالْعَدُوَّ اَوْقَعَ بِھِمْ لَیْلًا مِنْ دُوْنِ اَنْ یَّعْلَمُوْا.جب قوم اس کی مفعول ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رات کے وقت بغیر ان کی اطلاع کے ان پر حملہ کر دیا.شب خون مارا.(اقرب) تفسیر.مطالبہ عذاب کا دوسرا جواب اس آیت میں عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ تم کو یہ بحث نہ کرنی چاہیے کہ عذاب آج آئے گا یا کل یا کب آئے گا.بلکہ دیکھنایہ چاہیے کہ تم عذاب کے مستحق ہو یا نہیں.اگر مستحق ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ضرور عذاب میں مبتلا ہو گے.اور اس صورت میں تمہیں اپنی حالت کو بدل کر عذاب
Page 133
دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم عذاب کے مستحق نہیں ہو تو بجائے یہ کہنے کے کہ عذاب کب آئے گا یہ ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ تمہارے اعمال اور تمہاری حالت عذاب کی مستحق ہی نہیں.اس لئے عذاب آہی نہیں سکتا.اہل مکہ کی تباہی کی طرف اشارہ بَیَاتًا اَوْنَھَارًا کے الفاظ میں ایک لطیف اشارہ اہل مکہ کی تباہی کی طرف کیا ہے.ان کے لئے دن کے وقت بھی عذاب مقدر تھا اور رات کے وقت بھی.بدر کے موقع پر وہ دن کے وقت تباہ کئے گئے.جو سب سے پہلی اصلی جنگ ہے اور جنگ احزاب کے موقع پر جو حقیقی طور پر آخری جنگ تھی رات کے وقت ان کی تباہی کے سامان پیدا کئے گئے.اس آیت میں رات کے عذاب کو مقدم اس لئے کیا گیا ہے کہ اس عذاب سے ان کا بالکل خاتمہ ہو جانے والا تھا.يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی پھر سکتی ہے اور عذاب کی طرف بھی.اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ١ؕ آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهٖ کیا پھر (بعد میں یعنی) جب وہ آجائے گا (تو اس وقت) تم اس پر ایمان لاؤ گے( اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوسکتا.اس وقت تو تَسْتَعْجِلُوْنَ۠۰۰۵۲ تم سے کہا جائے گا کہ) کیا اب (تم ایمان لاتے ہو) حالانکہ (اس کے آنے تک) تم اس کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے رہے ہو.تفسیر.یعنی نشان کی غرض تو فائدہ اٹھانا ہوتی ہے.لیکن تم لوگ جو عذاب طلب کرتے ہو تمہاری کیا غرض ہے.کیا عذاب آنے پر ایمان لاؤ گے؟ لیکن اس وقت کا ایمان نفع نہیں دیا کرتا.بلکہ اس وقت تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب ایمان کا فائدہ نہیں.اب تو اس عذاب کے چکھنے کا وقت ہے جس کے جلدی نازل ہونے کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے.عذاب مانگنے والوں کے رد میں یہ کیسی زبردست دلیل ہے.نشان تو فائدے کے لئے ہوتے ہیں.لیکن عذاب کا نشان اس کے لئے جو عذاب مانگتا ہے فائدہ کا موجب نہیں ہوسکتا.ہاں! دوسروں کو نفع دیتا ہے.مگر ایک شخص جو خود تباہ ہوجائے اور خدا تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جائے تو اسے دوسروں کے نفع پانے سے جو کہ خود مشکوک ہے کیا فائدہ؟
Page 134
ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ١ۚ هَلْ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ہو گا انہیں کہا جائے گا (کہ اب) تم قائم رہنے والا عذاب پاؤ.تمہیں بدلہ میں اس کے سوا جو تم تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ۰۰۵۳ (خود) کماتے تھے کچھ نہیں دیا جاتا.حلّ لُغَات.اَلْـخُلْدٌ.خُلْدٌ کے معنی عربی زبان میں یہ ہوتے ہیں کہ اَلْبَقَاءُ باقی رہنا.اَلدَّوَامُ چلتے ہی چلے جانا.(اقرب) خَلَدَ یَخْلُدُ خُلوْدًا دَامَ و بَقِیَ.خُلْد کا فعل خَلَدَ ہے جس کے معنی ہیں رہا.دائم رہا.باقی رہا.اَلرَّجُلُ خَلْدًاوَ خُلُوْدً اأَبْطَأَ عَنْہُ الْمَشِیْبُ وَقَدْ اَسَنَّ.جب اس کا فاعل انسان ہو اور اس کی مصدر خَلْد یا خلود ہو تو ا سکے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی اور بڑھاپا نہ آیا.وَبِالْمَکَانِ وَاِلَی الْمَکَانِ اَقَامَ بِہٖ اور جب اس کے بعد ب یا اِلٰی آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فلاں مکان میں ٹھہرا.خَلَدَ اِلَی الْاَرْضِ لَصِقَ بِہَا وَاطْمَئَنَّ اِلَیْہَا اور اس کے بعد ایک معنی یہ بھی ہیں کہ وہ زمین سے چمٹ گیا اور اس پر مطمئن ہو گیا.(اقرب) تفسیر.عَذَابَ الْخُلْدِ کے یہ معنی ہوئے کہ وہ عذاب آئے گا جو ٹک جائے گا.اور تم سے چمٹ جائے گا.اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی ہٹے گا نہیں اور وہ غیر مقطوع ہو گا.بلکہ عذاب کے تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کیا گیا ہے.یعنی جب عذاب آئے گا تو ہٹایا نہ جائے گا جس طرح صاحب مکان جب آجائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ یہاں گنجائش نہیں.اسی طرح وہ عذاب ہوگا کہ اسے رد نہ کیا جاسکے گا.وَ يَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ١ؔؕ قُلْ اِيْ وَ رَبِّيْۤ اِنَّهٗ لَحَقٌّ١ؔؕۚ وَ اور وہ تجھ سے دریافت کرتے ہیں( کہ) کیا وہ( عذاب سچ مچ) واقع ہو گا.تو (انہیں )کہہ (کہ) ہاں.مجھے اپنے مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَؒ۰۰۵۴ رب کی قسم ہے کہ وہ یقیناً واقع ہونے والا ہے اور تم (ایسا کرنے سے خدا تعالیٰ کو) عاجز نہیں کر سکتے.حلّ لُغَات.اِی اِیْحرف جواب.بمعنی نَعَمْ.ہاں وَلَا تَقَعُ اِلَّا قَبْلَ الْقَسْمِ.یہ ہمیشہ قسم سے
Page 135
پہلے واقع ہوتا ہے.(اقرب) تفسیر.جب شریر آدمی بالکل بند ہو جاتا ہے تو ہنسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے.فرمایا کہ جب یہ لوگ ان دلائل سے عاجز آجائیں گے تو ہنسی کرنے لگیں گے اور بڑی سنجیدہ شکلیں بنا کر پوچھیں گے کہ کیا یہ باتیں سچی ہیں تو ان کی ہنسی کی پرواہ نہ کیجیؤ.اور کہہ دیجیؤ کہ ہاں! میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ باتیں سچی ہیں.اس جگہ سوال سے مراد قومی عذاب کے متعلق سوال ہے.جیسا کہ دوسری جگہ ہے عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ۠.عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ.(النباء:۲) صفت رب کی قسم کیوں کھائی گئی ہے لفظ رَبِّيْۤ میں رب کی صفت کی قسم کھاکر خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی حالت کو بطور دلیل پیش کیا ہے.اور وہ اس طرح پر کہ کفار کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے اسے رسول بنا کر کس طرح آہستہ آہستہ ترقی دی ہے.اور بتدریج وہ اسے بڑھا رہا ہے.اور تمہارے زور کو کم کررہا ہے پس اس سے تم بآسانی سمجھ سکتے ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جیت جائے گا اور تم ہار جاؤ گے.اس لئے تمہارا اس پیشگوئی پر تمسخر اڑانا تمہاری کم عقلی پر دلیل ہے ورنہ اگر ذرہ سی بھی عقل سے کام لو تو تم کو اس کے صحیح ہونے میں ذرہ بھی شبہ نہیں ہوسکتا.وَ لَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ اور اگر ایسا ہوتا کہ جو کچھ زمین میں( پایا جاتا) ہے وہ سب کا سب ہر ایسے شخص کا ہوتا جس نے ظلم کیا ہے.تو وہ ضرور اس بِهٖ١ؕ وَ اَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ١ۚ وَ قُضِيَ کے ذریعہ سے اپنے آپ کو( عذاب سے) چھوڑاتا.اور جب وہ (اس)عذاب کو دیکھیں گے تو وہ (اپنی )شرمندگی کو بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ۰۰۵۵ چھپائیں گے.اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا.اور ان پر( کوئی)ظلم نہیں کیا جائے گا.حلّ لُغَات.اسرَّ.اَسَرُّوْا النَّدَامَۃَ کے دو معنی ہوسکتے ہیں.ندامت کو چھپائیں گے.یا یہ کہ ان کے د لوں میں ندامت پیدا ہو جائے گی.اقرب میں ہے اَسَرَّالسِّرُّ کَتَمَہٗ.اسے چھپایا.اَظْھَرَہٗ اسے ظاہر کیا.
Page 136
ضِدٌّ یہ لفظ دو متضاد معنی دیتا ہے.تفسیر.انسانی فطرت اس قسم کی ہے کہ سزا کا اس پر دو قسم کا اثر ہوتا ہے.بعض شخص سزا پر اکڑ جاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں.اور بعض لوگ بالکل گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری سزا ایسی نہیں کہ اس کا اثر مشکوک ہو.بلکہ اس کا اثر یقینی ہوتا ہے اور ہر اک شخص خواہ کوئی ہو ہمارے عذاب کی برداشت سے عاجز آجاتا ہے.اور کسی میں بھی تکبر باقی نہیں رہتا.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو سزائیں دیتے ہیں ان کا اثر صرف جسم پر پڑتا ہے اور دل کو وہ مرعوب کرنے کی طاقت نہیں رکھتے.صرف بزدل آدمی اپنی کمزور فطرت کے ماتحت مرعوب ہوتے ہیں.لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں پر بھی قابض ہے اس کی سزا نہ صرف جسم پر نازل ہوتی ہے بلکہ دلوں پر بھی اور اس طرح دلوں کو پاک کیا جاتا ہے.پس فرمایا کہ ہماری سزا جب نازل ہوتی ہے تو دل بھی مرعوب ہو جاتے ہیں.اور جس پر عذاب نازل ہو وہ ہر قسم کی قربانی کرکے اپنے آپ کو بچانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے.ظاہری سبب بھی خدا تعالیٰ کی سزا سے مرعوب ہونے کا موجود ہوتا ہے جو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی سزا ہمیشہ مناسب موقع پر نازل ہوتی ہے.اور اس وجہ سے اس کی صحت کے دل قائل ہوتے ہیں.انسانی سزا غلط بھی ہوتی اور اور ایسے موقع پر ہی دل مقابلہ کے لئے تیار ہو تا ہے.جب وہ سزا کو ظالمانہ سمجھے.پس خدا تعالیٰ کے عادل ہونے کے سبب سے دل اس کے انصاف کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں.اور جب ندامت پیدا ہو تو انسان اپنے فعل کے ازالہ کی کوشش کرتا ہے.یہ بھی مطلب اس آیت کا نکلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب انہی پر آتا ہے جو اس کی تعلیم کا مقابلہ کرتے ہیں اور جو لوگ سچائی کا مقابلہ کریں ان کا کوئی ایسا آئیڈیل یا مقصد عالی نہیں ہوتا.جس کی خاطر وہ قربانی کررہے ہوں.بلکہ ادنیٰ خواہشات ہی ان کی مخالفت کی محرک ہوتی ہیں.اور یہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ کوئی مقصد عالی نہیں رکھتے وہ بڑی قربانی بھی نہیں کرسکتے اور کمینگی اور دنایت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر ہمارا عذاب آتا ہے وہ چونکہ ادنیٰ خواہشات کے شکار ہوتے ہیں بلند حوصلگی نہیں دکھاسکتے اور تکلیف کے وقت ہر اک چیز کو قربان کرکے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یعنی وہ چیزیں جنہیں انسان اپنی جان دے کر بھی بچاتا ہے یعنی قومی عزت وغیرہ وہ انہیں بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور یہ ثبوت ہوتا ہے ان کی غلطی پر ہونے کا.اگر وہ حق پر ہوتے تو کبھی ایسا کمینہ فعل نہ کرتے.
Page 137
َلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ اَلَاۤ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ سنو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں (پایا جاتا) ہے وہ سب( کا سب) یقیناً اللہ (تعالیٰ ہی) کا ہے.سنو اللہ (تعالیٰ) کا وعدہ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ۰۰۵۶ یقیناً پورا ہونے والا ہے.مگر ان میں سے اکثر (لوگ) نہیں جانتے.تفسیر.زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب خدا تعالیٰ کا ہے.اسے یا اس کے نیک بندوں کو فدیئے دے کر خوش کرنے کی کوشش بالکل لغو ہوتی ہے.وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتے.اہل مکہ نے چاہا کہ شرک کے خلاف وعظ کو روکیں.اور اس کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی لالچ دی لیکن آپ نے یہی جواب دیا کہ خواہ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو بائیں لاکھڑا کرو میں تو شرک کے خلاف وعظ کرنا نہیں چھوڑوں گا(سیرة النبی لابن ہشام زیر عنوان مُبَادَاۃ رسول اللہ قومہ...).اور اس طرح توحید کی کامیابی کے دن کو پیچھے نہیں ڈالوں گا اسی طرح جب ایران نے مسلمانوں سے جنگ شروع کی اور اس کا جواب دینے کے لئے اسلامی لشکر ایران کے علاقہ میں گھس گیا تو ایرانیوں نے روپیہ دے کر صلح کرنی چاہی لیکن خدا تعالیٰ کے وعدے پورے کرنے کے لئے مسلمانوں نے ان کے اموال کو ٹھکرا دیا(تاریخ الطبری احداث السنة الرابع عشرة للھجرة ).اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ چونکہ خودمحتاج ہوتے ہیں فدیوں پر خوش ہوجاتے ہیں.لیکن خدا تعالیٰ تو اموال کا خالق ہے اس کے سامنے فدیئے کچھ حیثیت نہیں رکھتے.سوائے اس کے کہ خود اپنے نفس کی قربانی ہو.اور وہ بھی اس لئے قبول کی جاتی ہے کہ وہ قربانی انسان کے نفس کو پاک کرنے کا موجب ہوتی ہے.هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۰۰۵۷ وہ زندہ کرتا ہےاور مارتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا یا جائے گا.تفسیر.یہ تعجب کرتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص کھڑا ہوکر کس طرح کامیاب ہوسکتا ہے.لیکن نہیں دیکھتے کہ روزانہ دنیا میں ترقی اور تنزل کے نظارے نظر آرہے ہیں.پھر کیا خدا کا رسول ہی کامیاب نہ ہوگا جس کی طرف یہ بھی اور دوسری مخلوق بھی فیصلہ کے لئے پیش کی جاتی ہے؟
Page 138
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یقیناً ایک( ایسی کتاب جو سراسر) نصیحت (ہے) اور( ہر) اس لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ١ۙ۬ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ۰۰۵۸ (بیماری) کےلئے جو سینوں میں (پائی جاتی) ہو شفا (کا سامان ہے) اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت (ہے) آئی ہے.حلّ لُغَات.مَوْعِظَۃٌ اَلْمَوْعِظَۃُنصیحت وَعَظَ کا اسم مصدر ہے.وَعَظَہٗ نَصَحَہٗ وَذَکّرَہٗ مَایُلَیِّنُ الْقُلُوْبَ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ.ایسی نصیحت کی جو دل کو نرم کر دے.کہیں سزا کی باتیں بتابتا کر اور کہیں کامیابی کے رستے بتا بتا کر.خلیل نحوی ادیب نے وعظ کے معنی ھُوَالتَّذْکِیْرُ بِالْخَیْرِ فِیْمَا یَرِقُّ لَہٗ الْقَلْبُ کئے ہیں یعنی وعظ ایسی باتوں کے یاد دلانے کو کہتے ہیں جن کے سننے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے.اَلْمَوْعِظَۃُ کَلَامُ الْوَاعِظِ مِنَ النُّصْحِ وَالْحَثِّ وَالْاِنْذَارِ مَوْعِظَۃٌ اس کلام کو کہتے ہیں جو نہایت اخلاص پر مبنی ہو.اور نیک باتوں کی طرف ترغیب دے اور بری باتوں سے ڈرائے.(اقرب) تفسیر.آنحضرت ؐ کی کامیابی کا راز مادی قوت میں نہیں بلکہ ان اعلیٰ کمالات میں مضمر ہے جن پر یہ کتاب مشتمل ہے پہلے تو ایک لطیف پیرایہ میں نصیحت کی کہ عذاب کی خواہش نہیں کرنی چاہیے.پس تم عذاب نہ مانگو.پھر مختلف طریقوں سے انہیں عذاب کی حکمتیں سمجھائی ہیں اور اب فرمایا کہ آؤ ہم تم کو بتائیں کہ یہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کس طرح کامیاب ہوگا؟ اس کی کامیابی کا راز فوجوں میں اور مال میں اور جتھے میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اس کی کامیابی تمام تر اس کتاب کے کمالات سے وابستہ ہے جو اسے ملی ہے.ایسی باکمال کتاب کا مقابلہ دیر تک نہیں کیا جاسکتا.آخر انسان اسی کی طرف لوٹنے پر مجبور ہوتا ہے.مَوْعِظَةٌ کی تفصیل جو کتاب اسے ملی ہےوہ موعظہ ہے.یعنی (ا) اس میں لوگوں کے فائدے کی باتیں ہیں جو اخلاص سے پر ہیں.اور اخلاص کا کلام آخر دل پر اثر کرکے ہی رہتا ہے.جس وقت تم غور کرو گے کہ اس کلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فائدہ بالکل نہیں اس کے ذریعہ سے مال یا عزت یا دبدبہ یا حکومت کچھ بھی اسے مطلوب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے میں صرف تمہارا ہی فائدہ ہے.تو خودبخود اس کی طرف توجہ کرو گے.
Page 139
(ب) دوسرے اس کے مطالب ایسے ہیں کہ جو دل کو نرم کرتے ہیں.اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی خشیت پر اس قدر زور ہے کہ سنگدل سے سنگدل انسان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا.(ج) اس میں تمہاری ترقی اور کامیابی کے گر بتائے گئے ہیں اور انہیں پیش بھی ایسے رنگ میں کیا گیا ہے کہ جس سے نفرت اور ضد نہ پیدا ہو بلکہ دل کو موہ لینے والا طریق اختیار کیا گیا ہے.شِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِکی تفصیل (۲) دوسرے یہ کتاب دلی شبہات کے لئے شفاء ہے.انسان خواہ کس قدر ہی گر جائے اس کی فطرت کبھی کبھی اس کے دل میں صداقت کے لئے تڑپ پیدا کر ہی دیتی ہے.اور حقیقت کے معلوم کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوہی جاتی ہے.اور خدا تعالیٰ اور الہام اور دعا اور معاد اور ایسے ہی دیگر امور کے متعلق وہ ایک اطمینان چاہتا ہے لیکن جھوٹے مذاہب یا نامکمل اور بگڑے ہوئے مذہب اس کی تسلی نہیں کرسکتے بلکہ ان سے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں اور اس وقت انسان خواہش کرتا ہے کہ کاش کوئی ایسی راہ ہو کہ دل ان شبہات سے پاک ہوسکے.اس وقت تم اس کلام میں تسلی پاؤ گے اور دیکھو گے کہ کس طرح امور ایمانیہ کے متعلق تمام شبہات کو یہ دور کرتا ہے اور خودبخود دل اس کی طرف مائل ہوں گے.ہدایت کی حقیقت (۳) شبہات کے دور کرنے کے علاوہ انسان جب بزرگان دین کے حالات پڑھتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ ایک اعلیٰ یقین اور قرب الٰہی کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے اور دین کی باریکیاں ان کو بتائی گئی تھیں اس وقت اس کا دل خواہش کرتا ہے کہ کاش میرا علمی ایمان بھی مشاہدہ کی صورت میں بدل جائے.اور میں بھی اپنی آنکھوں سے ان امور کو دیکھوں جن کو پہلے بزرگ دیکھتے چلے آئے ہیں.یہ خواہش بھی بہت سے لوگوں کے دلوں کو بے تاب کئے رکھتی ہے.پس اس حالت میں مبتلا لوگ بھی اس کتاب میں تسلی پائیں گے.اور حقیقی ہدایت ان کو ملے گی.جو بندہ کو خدا تعالیٰ سے ملا دیتی ہے.اور جب لوگ دیکھیں گے کہ اس کتاب پر چل کر خدا مل سکتا ہے بغیر اس کے نہیں تو خود بخود اس کے قبول کرنے کی طرف متوجہ ہوں گے.رحمت یعنی خاص فضل (۴) بعض لوگ ایسی موٹی عقل کے ہوتے ہیں کہ وہ علوم اور وجدان کی باریکیوں کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے.مگر مادی ترقیات ان کی توجہ کو کھینچ لیتی ہیں.سو ایسے لوگوں کی ہدایت کے لئے اس کتاب کے ساتھ خدا تعالیٰ کے خاص فضل بھی وابستہ ہیں جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ خاص فضل کرے گا اور ان کو دنیوی ترقیات بھی عطا فرمائے گا.پس عوام الناس جو چیز کی حقیقت دیکھنے کے بجائے اس کے اثرات اور نتائج کو دیکھا کرتے ہیں ان ترقیات کو دیکھ کر جو اسلام سے وابستہ ہیں اسلام میں داخل ہوں گے اور انہی انعامات کو
Page 140
حاصل کرنے کے خواہش مند ہوں گے.یہ چار امور ایسے ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی ترقی بلکہ کل سچے دینوں کی ترقی انہی کے ذریعہ سے ہوئی ہے جو بہت ہی حساس لوگ تھے انہوں نے محض اس کی مخلصانہ تعلیم کو دیکھ کر ہی فائدہ اٹھا لیا.جو ان سے سخت تھے انہوں نے عقلی دلائل سے تسلی پائی.جو ان سے بھی سخت تھے انہوں نے مسلمانوں کی اخلاقی حالت میں تبدیلی اور تعلق باللہ کی حالت کو دیکھ کر نصیحت حاصل کی جو اور بھی سخت تھے انہوں نے اسلام کی ترقیات کو دیکھ کر اس کی سچائی کا یقین کیا اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے.لِمَا فِي الصُّدُوْرِ.اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خیالات تو دماغ میں پیدا ہوتے ہیں.پس سینوں والی بات یا دل کی بات کو اچھا کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ روحانی امور دل کے ساتھ ایک باریک تعلق رکھتے ہیں اور تمام روحانی لوگوں کا تجربہ ہے کہ دل کا روحانیات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے.جس طرح روح کا علم مادیات سے معلوم نہیں ہوسکتا اور اس کا تعلق جو جسم سے ہے وہ دریافت نہیں ہوسکتا اسی طرح یہ بات بھی مادی قواعد سے دریافت نہیں ہوسکتی کہ دل سے روح کا کیا تعلق ہے.پس اس معاملہ میں ہمیں تجربہ کاروں کے مشاہدہ پر یقین کرنا پڑے گا جو بالاتفاق اس امر کے گواہ ہیں کہ دل کا تعلق روحانی امور سے ضرور ہے.اور خیالات کا دماغ میں پیدا ہونا اس کے مخالف نہیں کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ خون کے بعض تغیرات خیالات کے اچھے ہونے یا برے ہونے پر خاص اثر رکھتے ہوں اور خون کا تعلق چونکہ دل سے ہے اس طرح دل بھی ایک مخفی اثر خیالات پر ڈالتا ہوا ور یہ تو ظاہر ہے کہ خوراک کا اثر انسان کے خیالات پر پڑتا ہے.اور وہ اثر خون کے سوا اور کسی طرح نہیں پڑ سکتا.پس ان معنوں میں دل بھی خیالات کا ایک منبع کہلا سکتا ہے.چنانچہ اس مضمون کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بیان بھی کیا ہے اور غذا کا نیک اعمال کے ساتھ گہرا تعلق بتایا ہے.چنانچہ فرمایا يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا (المؤمنون:۵۲)یعنی پاکیزہ خوراک اعمال صالحہ کی توفیق کا ایک ذریعہ ہے.قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا١ؕ هُوَ تو( ان سے) کہہ (کہ یہ سب کچھ) اللہ (تعالیٰ) کے فضل سے اور اس کی رحمت سے (وابستہ )ہے پس اسی پر انہیں خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ۰۰۵۹ خوشی منا نا چاہیےجو( مال) وہ جمع کر رہے ہیں اس سے یہ( نعمت کہیں) زیادہ بہتر ہے.تفسیر.یعنی یہ نعمت جو اوپر بیان ہوئی ہے صرف خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوسکتی ہے کوئی انسان
Page 141
اپنے زور سے اسے حاصل نہیں کرسکتا.پس جو شخص خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ظاہری دولت اور جتھے پر گھمنڈ نہ کرے.کہ یہ چیزیں خدا کے فضل سے حاصل ہونے والی چیزوں کے مقابلہ میں کچھ بھی ہستی نہیں رکھتیں.بلکہ اس کا فخر اور اس کی خوشی انہی امور کے متعلق ہونی چاہیے جن کی صحت اور جن کے فائدے کا خدا تعالیٰ خود ضامن ہو.ھُوَ کی ضمیر کا مرجع هُوَ خَيْرٌ میں ھُوَ کی ضمیر فضل کی طرف بھی جاسکتی ہے اور فضل اور رحمت کے حاصل ہونے کے متعلق بھی ہوسکتی ہے اور اس سے مراد قرآن کریم بھی ہوسکتا ہے.جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ تم اپنے اموال اور جتھوں پر گھمنڈ کرکے پوچھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کامیابی ہوگی.مگر یاد رکھو کہ جو ہتھیار اسے ملا ہے یعنی قرآن کریم وہ تمہارے سب اموال و اولاد پر بھاری ہے.اور ان سے بہتر ہے اور اس کتاب کے مقابلہ پر تمہاری دولت و حشمت کچھ بھی نہ کرسکے گی یہی جیتے گا.سچائی انجام کار مادیات پر غالب آجاتی ہے کیا ہی عظیم الشان سچائی بتائی ہے کہ سچائیاں مادیات پر غالب ہوتی ہیں.ایک وقت میں سچائی سب سے کمزور نظر آتی ہے لیکن آخر وہ سب چیزوں پر غالب ہو کر رہتی ہے.اگر لوگ اس نکتہ کو سمجھیں تو مادی اشیاء کو صداقتوں پر کبھی ترجیح نہ دیں.قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ تو( ان سے) کہہ( کہ) کیا تم نے اس بات کو( بھی کبھی سوچ کر) دیکھا ہے کہ اللہ( تعالیٰ) نے تمہارے لئے مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا١ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ (آسمان سے) رزق اتارا پھر تم نے اس میں سے (کچھ) حرام اور( کچھ) حلال ٹھہرادیا.تو (ان سے) کہہ (کہ) تَفْتَرُوْنَ۰۰۶۰ کیا اللہ( تعالیٰ) نے تمہیں (اس بات کی )اجازت دی ہے یا تم اللہ (تعالیٰ) پر افتراء کرتے ہو.حلّ لُغَات.مَا استفہامیہ أَرَءَ یْتُمْ کے بعد ما مصدر یہ یا موصولہ کا آنا اور اس کے بعد پھر استفہام کا آنا بتاتا ہے کہ اس جگہ أَرَءَ یْتُمْ بمعنی اَخْبِرُوْنِیْ نہیں ہے.بلکہ اپنے اصلی معنی استفہامی میں ہے.
Page 142
تفسیر.قرآن کریم کی تعلیم کے مقابل پر تمہارے حلت و حرمت کے احکام کسی اصل پر مبنی نہیں چونکہ پہلے یہ بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب ملی ہے جو لوگوں کے دلوں کے شکوک کو بدل دے گی اب اس کے ثبوت میں ایک حکم بیان فرماتا ہے جو کفار میں رائج تھا اور جس کو لوگ صرف اس وجہ سے مانتے تھے کہ باپ دادا سے سنتے چلے آئے ہیں ورنہ عقلیں اس کو تسلیم کرنے کے لئےتیار نہ تھیں.اور وہ حلت و حرمت کا حکم تھا.کھانا پینا انسان کی پہلی ضرورتوں میں سے ہے اور اس کے متعلق صحیح رہنمائی کرنا مذہب کا پہلا فرض ہے.لیکن کفار مکہ کے پاس بلکہ دنیا بھر کے پاس اس کے متعلق کوئی صحیح راہنمائی نہ تھی جس چیز کو چاہا حرام کر دیا اور جس چیز کو چاہا حلال کر دیا.نہ کوئی قانون تھا نہ قاعدہ.اس بے اصولی تعلیم کو کون سی عقل تسلیم کرسکتی ہے.آخر حرمت کے لئے کوئی طبی یا اخلاقی یا مذہبی دلیل چاہیے.کسی چیز کو یا طبی نقائص کی وجہ سے حرام کیا جاسکتا ہے یا اخلاقی نقائص کی وجہ سے یا پھر روحانی امور کے سبب سے لیکن بلا کسی وجہ کے آپ ہی حرام کر دینا اور آپ ہی حلال کر دینا خدا تعالیٰ کی پیدائش کو باطل قرار دینا ہے.اور اس حلت و حرمت کے قواعد کے متعلق ضرور انسانوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوں گے.مگر ان شکوک کو سوائے اس مذہب کے کون دور کرسکتا ہے؟ جس نے حلال و حرام کے قواعد مقرر کئے ہیں اور ان قواعد کے رو سے کہ جن کو ہر عقل سلیم تسلیم کرسکتی ہے.وہ مختلف اشیاء کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے.اسلام کو تمام دیگر مذاہب پر یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ حلال و حرام کے اس نے قواعد مقرر کئے ہیں اور بلاوجہ صرف اظہار حکومت کے لئے اس نے چیزوں کو حلال یا حرام نہیں قرار دیا.قرآن کریم وہی چیزیں چھڑواتا ہے جو بہرحال تمہیں چھوڑنی ہی تھیں اس جگہ اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آخر اسلام کی مخالفت کی وجہ کیا ہے.وہ کون سی چیز ہے جو وہ تم سے چھڑواتا ہے لیکن وہ مفید ہے.اپنی حلال و حرام ہی کی تعلیم لے لو.کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے چھڑوانے پر اس قدر واویلا کیا جائے.اگر قرآن نہ بھی آتا تب بھی ایسی بیہودہ تعلیم کو تم آخر چھوڑ ہی دیتے.پس اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر تمہیں خوش ہونا چاہیے نہ کہ ناراض.اس آیت میں رَأَيْتُمْ متعدی بیک مفعول ہے.جو مَآ ہے اور جائز ہے کہ متعدی بدو مفعول ہو اور اس میں دو سرا قُلْ اور ہمزہ پہلے قُلْ اور ہمزہ کی تاکید کے لئے آئے ہوں اور رَأَیْتُمْ کا مفعول ثانی اَذِنَ لَکُمْ ہو اور اَمْ منقطعہ ہو.
Page 143
وَ مَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ اور جو لوگ اللہ( تعالیٰ) پر جھوٹ باندھتے ہیں.ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے.الْقِيٰمَةِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اللہ( تعالیٰ) لوگوں پر یقیناً (بہت ہی بڑے) انعام کرنے والا ہے اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَؒ۰۰۶۱ مگر ان میں سے اکثر (لوگ) شکر نہیں کرتے.حلّ لُغَات.یَوْمَ الْقِیَامَۃِ میں یوم ظرف کی وجہ سے منصوب ہے.اور فِیْ اس جگہ محذوف ہے.یعنی قیامت کے دن (قیامت کے متعلق) ان کا کیا گمان ہوگا.تفسیر.اس فضل کا انکار ظاہر کرتا ہے کہ انہیں قیامت پر بھی ایمان نہیں یعنی اگر خدا تعالیٰ پر ایمان ہو تو انسان اس پر جھوٹ کب بول سکتا ہے.پس ان امور کو جزوی قرار دے کر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے.یہ علامتیں ہیں اس امر کی کہ قیامت پر ایمان نہیں رہا.اور اللہ تعالیٰ کی صفات نظر سے اوجھل ہو گئی ہیں.ورنہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے فضل کے سامان پیدا کرے اور یہ لوگ ان کی ناقدری کریں.اور عقل کے خلاف ڈھکوسلوں کو خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم پر ترجیح دیں؟ قیامت کا دن عذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ انعامات اور ترقی کے لئے ہے ایک معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ اس جگہ ان کے مذہب کی خرابی اور خلاف عقل ہونے کی دوسری دلیل دی ہے.یعنی قیامت کا انکار.اور بتایا ہے کہ قیامت کا انکار محض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ گناہ گار فطرت اس دن کا خیال کرکے کانپتی ہے.جب اسے سزا ملے گی.اس لئے وہ اس کا انکار ہی کر دیتی ہے.حالانکہ انکار سے حقائق نہیں بدل جاتے.لیکن فرماتا ہے کہ یہ امر بھی عقل کے خلاف ہے کیونکہ قیامت کا وجود تو اللہ تعالیٰ نے ترقیات کے لئے بنایا ہے نہ دکھ دینے کے لئے.امتحان مدارس میں اس لئے رکھا جاتا ہے کہ بچے اس کی وجہ سے محنت سے کام کریں.بےشک بعض فیل ہو جاتے ہیں مگر امتحان کی غرض فیل کرنا نہیں بلکہ پاس کرنا ہے.پس جو شخص امتحان کو برا کہتا ہے وہ نادان ہے.اسے کس نے کہا ہے کہ وہ فیل ہو جائے وہ کوشش کرے کہ پاس ہو.آپ ہی فیل ہونے کے سامان پیدا
Page 144
کرنااورپھر امتحان کے نتائج سے ڈر کر اس کا سرے سے ہی انکار کر دینا تو اور بھی غافل اور سست کر دے گا اور تباہی سے بچائے گا نہیں بلکہ تباہی کی طرف دھکیل دے گا.وَ مَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّ مَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّ لَا اور تو نہ( کبھی) کسی کام میں (مشغول )ہوتاہے اورنہ تو اس( کتاب) میں سے کوئی حصہ قرآن پڑھتا ہے اور نہ تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ (ہی) تم( لوگ) کوئی (اور) کام کرتے ہو.مگر (اس حال میں کہ) جب تم اس میں تیزی سے مشغول ہوتے ہو تو تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ١ؕ وَ مَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ہم تمہیں دیکھ رہےہوتے ہیں.اور زمین یا آسمان میں کوئی( ایک) ذرہ بھر چیز(بھی) تیرے رب( کی نظر) سے ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ وَ لَاۤ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لَاۤ پوشیدہ نہیں ہوتی.اور نہ( ہی) کوئی (ذرہ سے) چھوٹی چیز ہے اورنہ (ہی اس سے) کوئی بڑی چیز ہے جو (ہر ایک اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ۰۰۶۲ حقیقت کو)روشن کر دینے والی ایک کتاب میں( مذکور اور موجود) نہ ہو.حلّ لُغَات.شَأْنٌ.اَلشَّأْنُ.الْخَطْبُ اَیْ مَاعَظُمَ مِنَ الْاَحْوَالِ وَالْاُمُوْرِ.اہم کام یا اہم بات.اہمیت رکھنے والی حالت.اَلْـحَالُ.حالت.صورت، صورتِ حال.اَلْاَمْرُ.معاملہ.بات.وَمِنْ شَأْنِہٖ کَذَا.اَیْ مِنْ طَبْعِہٖ وَخَلْقِہٖ کذا طبعی بات.عادت.معمول (اقرب).اس آیت میں پہلے معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں.اور اس میں اہم کاموں سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی اور دینی مشاغل ہیں.کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم کام یہی تھا.اَفَاضَ تُفِیْضُوْنَکی ماضی اَفَاضَ ہے.اَفَاضَ الْمَآءَ عَلٰی جَسَدِہٖ.اَفْرَغَہٗ انڈیلا ڈالا.اَفَاضَ دَمْعَہٗ سَکَبَہٗ بہایا.اَفَاضَ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ.اِنْدَفَعُوْا وَرَجَعُوْا.تَفَرَّقُوْا وَاَسْرَعُوْا مِنْہَا اِلَی مَکَانٍ اٰخَرَ.
Page 145
واپس ہو کر چلے گئے.تیزی کے ساتھ منتشر ہو گئے.اَفَاضَ الْقَوْمُ فِی الْحَدِیْثِ.اِنْدَفَعُوْا وَاَسْرَعُوْا.باتوں میں لگ گئے.اَفَاضَ فُلَانٌ اَلْاِنَاءَ.مَلَأَہٗ حَتّٰی فَاضَ.اس قدر لبریز کر دیا کہ بہہ پڑا.اَفَاضَ الْقِدَاحَ وَبِالْقِدَاحِ وَعَلَی الْقِدَاحَ.ضَرَبَ بِہَا جوا کھیلا.اَفَاضَ بِالشَّیْءِ دَفَعَ بِہٖ وَرَمٰی پھینکا.اَفَاضَ الْقَوْمُ عَلَی الرَّجُلِ.غَلَبُوْہُ.دبا لیا.مَااَفَاضَ بِکَلِمَۃٍ مَااَفْصَحَ بِہَا.خوب وضاحت سے بولا.(اقرب) یہ لفظ عام طور پر باتوں کے متعلق آتا ہے مگر یہاں پر عمل اور قول دونوں کے متعلق آیا ہے کیونکہ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب دو چیزوں کے لئے جدا جدا فعل ہوں تو کبھی قاعدہ تغلیب کے ماتحت ایک کو دوسرے کے تابع بنا کر دونوں کے لئے ایک ہی فعل لایا جاتا ہے.جیسے چار پائے کو چارہ دینے کے لئے عَلَفَ آتا ہے.اور پانی دینے کے لئے اَسْقَا آتا ہے مگر بجائے عَلَفْتُ الدَّآبَّۃُ تِبْنًا وَ اَسْقَیْتُہٗ مَآءً کے عَلَفْتُ الدَّآبَّۃ تِبْنًا وَمَآءً بول دیتے ہیں.پس اسی کے مطابق یہاں قول و عمل ہر دو کے لئے تُفِیْضُوْنَ ہی استعمال کیا گیا ہے.عَزْبٌ عَزَبَ الشَّیْءَ عَنْہُ یَعْزُبُ وَیَعْزِبُ عُزُوْبًا.بَعُدَ وَغَابَ وَخَفِیَ.دور ہوا.غائب ہوا.چھپا.یُقَالُ عَزَبَ عَنْہُ حِلْمُہُ.اَیْ غَابَ.اس کا علم جاتا رہا.غائب ہو گیا.عَزَبَ الرَّجُلُ.ذَھَبَ چلا گیا.(اقرب) مِثْقَالٌ اَلْمِثْقَالُ مَا یُوْزَنُ بِہٖ تولنے کا بٹہ وغیرہ.مِثْقَالُ الشَّیْءِ.مِیْزَانُہٗ مِنْ مِّثْلِہٖ برابر.ذَرَّۃٌ اَلذَّرَۃٌ وَاحِدَۃٌ الذَّرِّ.صِغَارُ النَّمْلِ چھوٹی چیونٹیاں.اَلْھَبَاءُ الْمُنْبَثُّ فِی الْھَوَآءِ ہوا میں ملا ہوا باریک غبار.تفسیر.مَا تَتْلُوْا مِنْهُ کی ضمیر کا مرجع مَا تَتْلُوْا مِنْهُ میں ضمیر مجرور کا مرجع قرآن کریم بھی ہوسکتا ہے اور اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تو نہیں پڑھتا قرآن کا کوئی حصہ.اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قد جاء تکم میںجس چیز کی آمد کی خبر دی گئی ہے اس کی طرف معناً ضمیر پھرتی ہو اور مراد یہ ہو کہ جو کلام ان لوگوں کی طرف قرآن کریم کی شکل میں آیا ہے اس میں سے تو جو کچھ پڑھتا ہے اور ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جاسکتی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پڑھتا ہے.ایک طرف آنحضرت ؐ سے خطاب اور دوسری طرف کفار سے یہ آیت بہت عجیب ہے.اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خداوند تعالیٰ عرش عظیم سے خطاب فرمارہا ہے.ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی جماعت ہے اور دوسری طرف مخالفین بیٹھے ہیں.پہلے حصہ آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو مخاطب کرتا ہے پھر مخالفین کی طرف توجہ کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَاتَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا.تم
Page 146
کوئی کام نہیں کرتے جس پر ہم نگران نہ ہوں.صغیر بھی غائب رہنے کا موجب ہوتا ہے اور کبیر بھی اَصْغَرَ کالفظ تو اس لئے لایا گیا ہے کہ چھوٹی چیز نظر سے غائب ہوسکتی ہے.مگر اکبر کا لفظ کیوں لایا گیا ہے؟ سرسری نگہ سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ تابع مہمل ہے.لیکن حقیقتاً ایسا نہیں.کیونکہ کبھی بڑی چیز بھی ادراک سے غائب ہو جاتی ہے.مثلاً آنکھ کے سامنے ایک بڑا پہاڑ آجائے تو اس کا صرف تھوڑا سا حصہ نظر آسکتا ہے.معلوم ہوا کہ صغیر ہونے کی وجہ سے بھی چیز غائب ہوسکتی ہے اور کبیر ہونے کی وجہ سے بھی.اس لئے فرمایا کہ اس کی نظر اس قدر وسیع ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی اس سے غائب نہیں ہوسکتی.اور اتنا لطیف ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس سے اوجھل نہیں ہوسکتی.علمی نظر سے اگر دیکھا جائے تو آنکھ اور کان کی مثال سے یہ امر خوب روشن ہو جاتا ہے علم النفس کے ماہروں کی تحقیق سے ثابت ہے کہ دیکھنا اور سنناکچھ حرکات متوالیہ متواترہ پر منحصر ہے.جنہیں وائبریشنز کہتے ہیں.آنکھ اور کان دونوں کے لئے ایک حد مقرر ہے.ایک حد سے کم حرکات کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور نہ ایک حد سے زیادہ کو.یہی حال کان کا ہے جو حرکت کہ ایک سیکنڈ میں تیس سے کم ہو کان اسے نہیں سن سکتے لیکن جو حرکت کہ سیکنڈ میں چالیس سے بڑھ جائے اسے بھی کان نہیں سن سکتے.پس علمی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ بعض چیزیں بڑی ہوکر بھی آنکھ یا کان کے ادراک سے نکل جاتی ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں.ہر چیز خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہمارے علم میں رہتی ہے.نجات کے لئے صرف ایمان کافی نہیں بلکہ نیت اور طریق عمل کی درستی بھی ضروری ہے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ گو تم دونوں فریق میں سے ایک خدا تعالیٰ کے دین پر ایمان لانے والا اور ایک مومن ہے لیکن دونوں فریق کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف صداقت کو مان لینا کافی نہیں ہوتا.بلکہ جزائے اعمال کے وقت نیت اور طریق عمل کو بھی مدنظر رکھا جاتا ہے.پس ہر وقت انسان کو اپنے نفس کا معائنہ کرنا چاہیے.کسی عظیم الشان کام کا کرنا یا خدا تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر سنانا اپنی ذات میں کافی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے اس کام کو کیا جاتا یا کلام کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور کس طریق پر کیا جاتا یا پڑھا جاتا ہے.ہوسکتا ہے کہ نیت خراب ہو یا ہوسکتا ہے کہ تبلیغ میں کوئی ایسا رنگ اختیار کیا جائے کہ لوگ بجائے قریب آنے کے دور ہو جائیں.اور انہیں ضد پیدا ہوجائے پس تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تم اس کام کو کس طرح کرتے ہو.کیا لوگوں کو دین سے اور بھی دور تو نہیں کررہے؟ مَا تَکُوْنُ کے خطاب میں مومنین بھی داخل ہیں یا د رکھنا چاہیے کہ گو اس جگہ الفاظ میں ایک شخص مخاطب
Page 147
ہے مگر مراد سب مسلمان ہیں.اور بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو قوموں میں مقابلہ شروع ہے.ایک طرف ہماری قائم کردہ جماعت ہے اور دوسری طرف کفار کی جماعت ہے ہم نے اپنی جماعت کا پاس اس لئے نہیں کرنا کہ وہ ہماری ہے.بلکہ نیت کو دیکھنا ہے.پس اے قرآن پڑھنے والو اگر تم نے نیک نیتی اور حکمت سے قرآن ان کو نہ سنایا اور اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا تو ہم تمہیں پکڑیں گے کیونکہ اس انکار کے ذمہ دار تم ہو گے.لیکن اگر تم نےاپنی طرف سے اشاعت قرآن کریم کے فرض کو باحسن وجوہ ادا کیا تو اے انکار کرنے والو! ہم تمہیں پکڑیں گے.گویا اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم صرف عمل کو ہی نہیں دیکھتے بلکہ اسباب اور موجبات کو بھی دیکھتے ہیں.اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَۚۖ۰۰۶۳ سنو جو( لوگ) اللہ( تعالیٰ) سے سچی محبت رکھنے والے ہیں.ان پر نہ کوئی خوف (مستولی ہوتا )ہے اور نہ وہ غمگین رہتے ہیں.حلّ لُغَات.اَلَٓا یہ تنبیہ کے لئے اور ہوشیار کرنے کے لئے آتا ہے.گویا کہ فرماتا ہے کہ اچھی طرح سن رکھو.اس جگہ اس کے معنی خبردار کرنا اردو محاورہ کے لحاظ سے صحیح نہیں.کیونکہ خبردار ڈرانے کے لئے آتا ہے.مگر یہاں تو ایک مبارک مضمون ہے.کیونکہ اولیاء کو خوشخبری دی گئی ہے.اس لئے خبردار رکھنے کا موقع نہیں.اس لئے اس کا ترجمہ ’’سنو‘‘ کیا گیا ہے.تفسیر.لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کے معنی لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کے معنوں میں لوگوں نے غلطی کی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں آتا.حالانکہ عربی زبان میں خِفْتُ عَلَیْکَ کے معنی ہوتے ہیں کہ میں ڈرا کہ تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے.اور خِفْتُ عَلٰی نَفْسِیْ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ میں ڈرا کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے.اس جگہ اس محاورہ کے مطابق یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے.صرف فرق یہ ہے کہ نسبت کو حذف کر دیا گیا ہے.اور مراد یہ ہے کہ لَایَخَافُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِہِمْ یعنی اپنے نفس کے متعلق یقین رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.نہ یہ کہ کوئی خطرہ انہیں پیش نہیں آئے گا.وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ کے معنی وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ سے یہ بتایا کہ ان کو ماضی کا بھی صدمہ نہ ہوگا.اس فقرہ میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کے صدمات سے بھی محفوظ رکھتا ہے.جو اعلیٰ مقامات کے حصول سے پہلے وہ کرچکے ہوں کیا ہی محفوظ مقام ہے دنیا کی کوئی طاقت آئندہ اور ماضی کا ذمہ نہیں لے سکتی.صرف
Page 148
اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس سے تعلق پیدا کرکے انسان کامل چین پاسکتا ہے.مگر افسوس !کہ لوگ اسی طرف سب سے کم توجہ کرتے ہیں.اور اپنے دردوں کا علاج ان دروازوں سے تلاش کرتے ہیں جہاں سے سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہیں ہوسکتا.انبیاء کا خوف و حزن بعض جگہ جو انبیاء کی نسبت خوف اور حزن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس جگہ خوف اور حزن ان کی اپنی ذات کے متعلق نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کی نسبت ہوتا ہے اور دوسروں کی نسبت خوف اور حزن کا پیدا ہونا عذاب نہیں کہلاسکتا.بلکہ یہ تو ایک اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے کہ انسان دوسروں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے.اور ان کے درد میں شریک ہو.انہی معنوں کے رو سے حزن کا لفظ حضرت یعقوب کے لئے استعمال ہوا ہے وہ حزن اپنی ذات کے متعلق نہ تھا.بلکہ اپنی اولاد کی نسبت تھا.جو گنہ گار ہوکر خدا سے دور جارہی تھی.اور یہ حزن عین رحمت تھا.اسی طرح حضرت زکریا کی نسبت آتا ہے اِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِيْ (مریم :۶).اپنے بعد میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ میرے کام کو خراب نہ کردیں.یہ خوف بھی ثواب کا موجب اور نیکی کا اعلیٰ نمونہ ہے کیونکہ یہ خوف اپنی ذات کی نسبت نہیں بلکہ اس امر کے متعلق ہے کہ لوگ گمراہ نہ ہوجائیں.الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَؕ۰۰۶۴ (یعنی وہ لوگ) جو ایمان لائے اور تقویٰ کو( ہمیشہ) لازم حال رکھتے تھے.تفسیر.اولیاء اللہ کی صفت حدیث میں اس آیت میں اولیاء کی صفت بتائی ہے کہ وہ ایمان میں کامل اور تقویٰ کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ولایت کی تشریح فرمائی ہے اور وہ گویا اس آیت کی تفسیر ہے.پس میں اسے بھی اس جگہ بیان کر دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں اِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَۃِ یُؤْتٰی بِاَھْلِ وِلَایَۃِ اللہِ فَیَقُوْمُوْنَ بَیْنَ یَدَیِ اللہِ عَزَّوَجَلَّ ثَلَاثَۃَ اَصْنَافٍ.فَیُؤْتٰی بِرَجُلٍ مِنَ الصِّنْفِ الْاَوَّلِ فَیَقُوْلُ عَبْدِیْ لِمَاذَا عَمِلْتَ فَیَقُوْلُ یَارَبِّ خَلَقْتَ الْجَنَّۃَ وَاَشْجَارَھَا وَاَثْمَارَھَا وَاَنْھَارَھَا وَحُوْرَھَا وَنَعِیْمَھَا وَمَااَعْدَدْتَ لِاَھْلِ طَاعَتِکَ فِیْہَا فَاسْہَرْتُ لَیْلِیْ وَأَظْمَأْتُ نَہَارِیْ شَوْقًا اِلَیْہَا قَالَ فَیَقُوْلُ اللہُ تَعَالٰی عَبْدِیْ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلْجَنَّۃِ ھٰذِہِ الْجَنَّۃُ فَاَدْخُلْھَا وَمِنْ فَضْلِی عَلَیْکَ اِنِّی قَدْاَعْتَقْتُکَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ فَضْلِیْ عَلَیْکَ اَنْ أُدْخِلَکَ جَنَّتِیْ فَیَدْخُلُ ھُوَوَمَنْ مَعَہُ الْجَنَّۃِ
Page 149
قَالَ ثُمَّ یُؤْتٰی بِرَجُلٍ مِنَ الصِّنْفِ الثَّانِیْ فیَقُوْلُ عَبْدِیْ لِمَاذَا عَمِلْتَ فَیَقُوْلُ یَارَبِّ خَلَقْتَ نَارًا وَخَلَقْتَ اَغْلَالًاوَخَلَقْتَ سَعِیْرَھَاوَسَمُوْمَھَاوَیَحْمُوْمَھَاوَمَااَعْدَدْتَّ لِاَعْدَائِکَ وَاَھْلِ مَعْصِیَتِکَ فِیْھَا فَاسْھَرْتُ لَیْلِیْ واظْمَأْتُ نَھَارِیْ خَوْفًا مِنْھَا فَیَقُوْلُ عَبْدِیْ اِنَّمَا عَمِلْتَ ذٰلِکَ خَوْفًا مِّنْ نَارِیْ فَاِنِّیْ قَدْاعْتَقْتُکَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ فَضْلِیْ عَلَیْکَ اَنْ أُدْخِلَکَ جَنَّتِیْ فَیَدْخُلُ ھُوَ وَمَنْ مَعَہُ الْجَنَّۃَ ثُمَّ یُؤْتِٰی بِرَجُلٍ مِنَ الصِّنْفِ الثَّالِثِ فَیُقُوْلُ عَبْدِیْ لِمَاذَا عَمِلْتَ فَیَقُوْلُ حُبًّالَکَ وَشَوْقًا اِلَیْکَ وَعِزَّتِکَ قَدْأَسْہَرْتُ لَیْلِیْ وَاظْمَأْتُ نَھَارِیْ شَوْقًا اِلَیْکَ وَحُبًّا لَکَ فَیَقُوْلُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی اِنَّمَا عَمِلْتَ حُبًّا لِیْ وَشَوْقًا اِلَّی فَیَتَجَلّٰی لَہُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُہُ فَیَقُوْلُ ھَااَنَا ذَا فَانْظُرْ اِلَیَّ ثُمَّ یَقُوْلُ مِنْ فَضْلِیْ عَلَیْکَ اَنْ أُعْتِقَکَ مِنَ النَّارِ وَأُبِیْحَکَ جَنَّتِیْ وَأُزِیْرَکَ مَلَائِکَتِیْ وَأُسَلِّمُ عَلَیْکَ بِنَفْسِیْ فَیَدْخُلُ ھُوَ وَمَنْ مَعَہُ الْجَنَّۃَ.یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو لایا جاوے گا اور وہ خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے.اور تین قسموں میں انہیں تقسیم کیا جائے گا.پہلے ایک قسم کا ایک آدمی لایا جائے گا.اسے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے! تو نے (نیک) اعمال کس وجہ سے کئے تھے؟ وہ عرض کرے گا.کہ اے میرے رب! آپ نے جنت پیدا کی اور اس کے درخت اور پھل پیدا کئے اور نہریں پیدا کیں اور اس کی حوریں اور اس کی نعمتیں اور جو کچھ بھی آپ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لئے طیار کیا ہے سب کچھ بنایا.پس میں نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے شب بیداری کی اور دن کو روزے رکھے.اس پر خدا تعالیٰ اسے فرمائے گا اے میرے بندے! تو نے صرف جنت کی خاطر نیک اعمال کئے سو یہ جنت ہے اس میں داخل ہو جا.اور یہ میرا فضل ہی ہے کہ میں نے تجھ کو آگ سے آزاد کردیا اور یہ بھی فضل ہے کہ میں تجھے جنت میں داخل کروں گا.پس وہ اور اس کے ساتھی جنت میں داخل ہوجائیں گے.پھر دوسری قسم کے آدمیوں میں سے ایک آدمی لایا جائے گا.اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے! تو نے (نیک) اعمال کس غرض سے کئے تھے؟ وہ جواب دے گا کہ اے میرے رب تو نے دوزخ پیدا کی اور اس کی بیڑیاں اور اس کی شعلہ زن آگ اور اس کی بادسموم اور گرم پانی.اور جو کچھ بھی تو نے اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کے لئے تیار کیا ہے پیدا کیا.پس میں نے ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے شب بیداری کی اور دن کو روزے رکھے.اس پر خدا تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے !تو نے یہ کام صرف میری آگ سے ڈرتے ہوئے کئے تھے.پس میں نے تجھے آگ سے آزاد کیا.اور اپنے فضل سے تجھے جنت میں داخل کروں گا.پس وہ اپنے ساتھیوں سمیت جنت میں داخل ہو جاوے گا.اس کے بعد
Page 150
تیسری قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا.اس سے خدا تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندے! تو نے (نیک) کام کس وجہ سے کئے تھے؟ وہ جواب دے گا اے میرے رب! تیری محبت کی وجہ سے اور تیرے ملنے کے اشتیاق میں.تیری عزت کی قسم میں راتوں کو جاگا اور دن کو میں نے روزے رکھے.صرف تیرے اشتیاق اور تیری محبت میں پس مبارک اور بلند و بالا خدا اسے فرمائے گا اے میرے بندے! تو نے یہ تمام نیک کام میری محبت اور میری ملاقات کے شوق کی وجہ سے کئے تھے سو اپنا بدلہ لے اور اللہ جل جلالہ اس شخص کے لئے خاص تجلی فرمائے گا اور سارے پردوں کو اپنے چہرے سے دور کر دے گا اور اس کے سامنے آجائے گا.اور کہے گا اے میرے بندے! لے میں یہ موجود ہوں.میری طرف دیکھ.پھر فرمائے گا میں نے اپنے فضل سے تجھے آگ سے آزا دکیا.اور جنت کو تیرے لئے جائز کرتا ہوں.اور فرشتوں کو تیرے پاس بھیجوں گا.اور میں خود تجھے سلام کہوں گا.پس وہ اپنے ساتھیوں سمیت جنت میں داخل ہو جائے گا.اولیاء اللہ کے سردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یہ جو اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھایا جائے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں میں سے جو کامل ترین اصناف میں سے ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے گا.اور گویا بطور نمائندہ کے اپنے حضور میں اسے بلائے گا.آخری جماعت جو سب سے کامل جماعت اور ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کو پہنچی ہوئی ہے اس کے قائم مقام یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کیونکہ آپ ہی وہ شخص ہوں گے جنہوں نے وفات کے وقت نہایت بے تابی سے کہا اَلرَّفِیْقُ الْاَعْلٰی الرَّفِیْقُ الْاَعْلٰی(بخاری کتاب المغازی باب آخر ما تکلم النبیؐ).یعنی میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں.اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں.اولیاء اللہ پر انبیاء و شہداء کا رشک کرنا اولیاء اللہ کے مختلف مدارج کے متعلق اور بھی بعض حدیثیں آئی ہیں.چنانچہ ایک روایت ابوداؤد میں آئی ہے.ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِنْ عِبَادِاللہِ عِبادٌ یَغْبِطُہُمْ الْاَنْبِیَآءَ وَالشُّہَدَآء قِیْلَ مَنْ ھُمْ یَارَسُوْلَ اللہِ لَعَلَّنَا نُحِبُّہُمْ قَالَ ھُمْ قَوْمٌ تَحَابَّوْا فِی اللہِ مِنْ غَیْرِ اَمْوَالٍ وَلااَنْسَابٍ.وُجُوْھُہُمْ نُوْرٌ عَلٰی مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ لَایَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا یَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ (ابوداؤد بہ حوالہ ابن کثیر جلد ۵ زیر آیت ہٰذا) یہ حدیث تفسیر ابن جریر میں بھی آئی ہے.صرف راویوں کا فرق ہے.یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بندے ہیں جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں.اس پر صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ! وہ کون ہیں تاکہ
Page 151
ہم بھی ان سے محبت کریں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہ لوگ ہیں جو صرف خدا تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں.مال یا رشتہ داری اس محبت کا موجب نہیں ہوتی.(کیا ہی عجیب زمانہ تھا کہ صحابہ نیکوں سے محبت کی خواہش کرتے تھے لیکن آج کل نیکوں سے لوگ بغض رکھتے ہیں) ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہرے منور ہوں گے نورانی ممبروں پروہ بیٹھے ہوں گے.دوسری ان کی علامت یہ ہے کہ جب لوگوں پر خوف آتا ہے تو وہ نڈر ہوتے ہیں.اور جب لوگ اپنی گزشتہ باتوں پر جزع فزع کررہے ہوتے ہیں تو وہ امن میں ہوتے ہیں.ولی اللہ بننے کی راہ اس حدیث میں اولیاء اللہ بننے کا طریق بتایا ہے اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی خاطر نبی کے ہاتھ پر جمع ہونے والی جماعت سے محبت کرے اور دنیا کی باتوں سے نڈر ہو.بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو.خدا تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے.ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان جیسے بننے کا یہ طریق ہے کہ آپس میں دلوں کے بغض نکال دیں.اور تفرقہ کو چھوڑ دیں.اور مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے رابطۂ اتحاد پیدا کریں.دنیا سے نہ ڈریں اور نہ مصائب سے گھبرائیں.نبیوں کے رشک کرنے کے معنی نبیوں کے رشک کرنے کا جو اس حدیث میں ذکر ہے اس سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ نبی ان لوگوں سے ادنیٰ درجہ کے ہوتے ہیں بلکہ رشک سے مراد یہ ہے کہ نبی چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے متبعین میں سے بکثرت ہوں.نہ یہ کہ وہ خود ایسے ہوجائیں کیونکہ کوئی نبی نہیں ہوسکتا جس میں یہ صفت پہلے ہی سے نہ پائی جائے.لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ١ؕ لَا ان کے لئے (اس) ورلی زندگی میں( بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے) بشارت( پانےکا انعام مقرر )ہے.اور بعد تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ١ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُؕ۰۰۶۵ والی( زندگی) میں بھی.اللہ (تعالیٰ) کی (فرمودہ) باتوں میں( قطعاً)کوئی تبدیلی نہیں (ہو سکتی) یہی (وہ کامیابی ہے جو بڑی) عظیم الشان کامیابی( کہلا سکتی )ہے.تفسیر.حدیث میں اس بُشْرٰی کی کئی تشریحیں آئی ہیں.بشریٰ کے معنی حدیث میں اول.عَنْ اَبِی الدَّرْدَآءِ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِی قَوْلِہٖ
Page 152
لَھُمُ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَۃِ.قَالَ الرُّؤْیَا الصَّالِحَۃُ یُرَاھَا الْمُسْلِمُ اَوْتُرٰی لَہٗ(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا).ترجمہ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ کے متعلق فرمایا کہ اس بشریٰ سے رؤیا صالحہ مراد ہے.جسے مومن اپنے متعلق خود دیکھتا ہے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے.دوم.تفسیر ابن جریر میں ابوالدرداء سے روایت آئی ہے.سَأَلَہٗ رَجُلٌ عَنْ ھٰذِہِ الْاٰیَۃِ فَقَالَ سَئَلْتَ عَنْ شَیْءٍ مَاسَمِعْتُ اَحَدًا سَأَلَ عَنْہُ بَعْدَ رَجُلٍ سَأَلَ عَنْہُ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم فَقَالَ ھِیَ الرُّوْیَا الصَّالِحَۃُ یَرَاھَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰی لَہٗ بُشْرَاہُ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا وَبُشْرَاہُ فِی الْاٰخِرَۃِ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا)یعنی ایک شخص نے ابوالدرداء سے اس آیت کے معنی پوچھے.انہوں نے (اس پر خوش ہوکر) کہا.آپ نے ایسی بات پوچھی ہے جو اس سے پہلے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی.جس کے بعد میں نے کسی اور سے یہ سوال نہیں سنا تھا.آپ نے جواباً فرمایا تھا کہ اس سے مراد رؤیا صالحہ ہے.جو ایک مسلمان شخص (خود) دیکھتا ہے یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھتا ہے.پس یہ اس زندگی میں بھی اس کے لئے بشارت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے بشارت ہے.سوم.عبادۃ بن الصامت سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا.آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا تِلْکَ الرُّؤْیَا الصَّالِحَۃُ یَرَاھَا الرَّجُلُ اَوْ تُرٰی لَہٗ (تفسیر ابن کثیرزیر آیت ھذا)یعنی اس سے مراد رؤیا صالحہ ہے جسے انسان خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے.چہارم.ایک اور روایت میں ہے.یَرَاھَا الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فِی الْمَنَامِ اَوْتُرٰی لَہٗ (تفسیر ابن کثیرزیر آیت ھذا) یعنی اس سے مراد رویا صالحہ ہے جسے خدا کا مومن بندہ خواب میں خود (اپنے متعلق) دیکھتا ہے یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھتا ہے.پنجم.عبادۃ بن الصامت کی ایک اور روایت ہے کہ لَقَدْ عَرَفْنَا بُشْری الْاٰخِرَۃِ الْجَنَّۃُ فَمَا بُشْرَی الدُّنْیَا قَالَ الرُّؤْیَا الصَّالِحَۃُ یَرَاھَا الْعَبْدُ اَوْ تُرٰی لَہٗ وَھِیَ جُزْءٌ مِّنْ اَرْبَعَۃٍ وَاَرْبَعِیْنَ جُزْءًا أَوْ سَبْعِیْنَ جُزْءًا مِّنَ النُّبُوَّۃِ.یعنی ہمیں آخرت کی بشریٰ کے متعلق تو علم ہو گیا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے.مگر دنیا کی بشریٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ رویا صالحہ ہے جو بندہ دیکھتا ہے.یا اس کی خاطر کسی اور کو دکھائی جاتی ہے اور وہ نبوت کا چوالیسواں یا سترھواں حصہ ہے.(ابن کثیر زیر آیت ھذا)
Page 153
لوگوں میں نیکی کے ساتھ شہرت بھی دنیا میںایک بشریٰ ہے ششم اسی طرح صحابہ کے اس سوال پر کہ اَلرَّجُلُ یَعْمَلُ العَمَلَ وَیَحْمَدُہُ النَّاسُ عَلَیْہِ وَیَثْنُوْنَ عَلَیْہِ بِہٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ تِلْکَ عَاجِلُ بُشْرَی الْمُؤْمِنِ(تفسیر ابن کثیرزیر آیت ھذا).یعنی ایک شخص عمل کرتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے اس کی تعریف اور ثناء کرتے ہیں کیا اسی کو اس کی نیکی کا بدلہ سمجھ لیا جائے.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو نیک بدلے ملنے والے ہیں انہی میں سے یہ ایک دنیوی بدلہ ہے.رؤیا صالحہ نبوت کا انچاسواں حصہ ہے ہفتم.عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ اَلرُّؤْیَا الصَّالِحَۃُ یُبَشَّرُہَا الْمُؤْمِنُ جُزْءٌ مِّنْ تِسْعَۃٍ وَأَرْبَعِیْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّۃِ.فَمَنْ رَأی ذٰلِکَ فَلْیُخْبِرْبِہَا وَمَنْ رَأَی سِوَی ذٰلِکَ فَاِنَّمَا ھُوَمِنَ الشَّیْطَانِ لِیَحْزُنَہٗ فَلْیَنْفُثْ عَنْ یَّسَارِہٖ (ابن کثیر زیر آیت ھٰذا) یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اس سے مراد خواب ہے.اور یہ انچاسواں حصہ نبوت کا ہے.پس جو ایسی خواب دیکھے وہ بے شک دوسرے کو بتادے.اور جو اس کے سوا یعنی بری خواب دیکھے اس کی وہ خواب شیطان کی طرف سے ہے تاکہ اس کو غم میں مبتلا کرے.پس اسے چاہیے کہ بائیں طرف تھوک دے.اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بری خواب کا بیان کرنا ناپسندیدہ ہے.حضرت مسیح موعود ؑ کی نبوت اس قسم کی نہیں بعض لوگوں نے غلطی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی کو بھی اسی قسم کا قرار دیا ہے.لیکن یہ غلط ہے کیونکہ ان خوابوں کے دیکھنے والوں کی بعض خوابوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی بھی قرار دیا ہے.مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو خدا تعالیٰ نے مامور کیا تھا جس کی کوئی خواب یا کوئی الہام شکی نہیں ہوسکتا.اور آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مجھے اپنے الہام پر ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ قرآن کریم پر.پس جو لوگ الہام کے منکر ہیں احادیث سے ان کو الہام کی ضرورت کا قائل کیا جاسکتا ہے.مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اس قسم کے الہام سے بالا کوئی اور چیز نہیں ہوتی.ہاں یہ سچ ہے کہ مبشرات کا لفظ عام ہے.اسے انبیاء کے الہامات کے لئے بھی بول سکتے ہیں.اور اولیاء کے الہام پر بھی.پس یہ آیت سب قسم کے الہاموں کی خبر دیتی ہے.ان میں سے جو صحابہ سے تعلق رکھتے تھے رسول کریم صلعم نے بیان کر دیئے.لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ کے معنی لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِمیں دو باتیں بتائی گئی ہیں.اول یہ کہ یہ خدا تعالیٰ کا قدیم قانون ہے اور چونکہ قدیم سے یہ قانون ہے اس لئے اب بھی ایسا ہوگا.دوم یہ کہ یہ وعدہ ہمارا ایسا ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ فیصلہ کرچکے ہیں کہ وہ بدلے گا نہیں.یعنی بعض امور غیبیہ کلمات اللہ میں شامل نہیں ہوتے.اور وہ بدل جاتے ہیں.لیکن بعض امور غیبیہ کلمات اللہ کہلاتے ہیں اور وہ ہرگز
Page 154
نہیں بدلا کرتے.ذٰلِكَ کا مشار الیہ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ یعنی خدا تعالیٰ سے بشارت کا ملنا ہی بڑی کامیابی ہوتا ہے یا یہ کہ کلمات اللہ کا تبدیل نہ ہونا یہی بڑی کامیابی ہے.دونوں معنی لئے جاسکتے ہیں.بشارت کا کامیابی ہونا تو ظاہر ہی ہے.کلمات اللہ کا نہ بدلنا کامیابی کا بہت بڑا گر ہے کلمات اللہ کا نہ بدلنا بھی کامیابی کا بہت بڑا گر ہے.دینی امور میں بھی اور دنیوی امور میں بھی.چنانچہ سائنس کی بنیاد ہی ایسے قوانین پر ہے جو نہیں بدلتے.قوانین نیچر بدلتے رہتے تو دنیا ہرگز ترقی نہ کرسکتی.اور ایجادات کا سلسلہ ہرگز نہ چلتا.آگ جلاتی ہے.پانی سیراب کرتا ہے.بجلی تباہ کرتی ہے.ہر ایک چیز کے قوانین علیحدہ علیحدہ ہیں اور یہ بدلتے نہیں ہیں.اگر یہ بدل جاتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی آگ جلانے لگتا تو آگ جلنے کی بجائے پانی پیدا ہو جاتا.اور آٹا ہی بھیگ جاتا یا لوگ پنکھا چلاتے تو آگ پیدا ہوجاتی تو دنیا کبھی قدرت کے ذخیروں سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ نہ کرتی.اور نظام عالم تباہ ہوجاتا.پس خدا تعالیٰ کے نہ بدلنے والے قوانین ہی کامیابی کی جڑ ہیں.انہی کے راز معلوم کرکے دنیا ترقی کررہی ہے.وَ لَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ١ۘ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا١ؕ هُوَ السَّمِيْعُ اور( چاہیے کہ) ان کی (کوئی مخالفانہ) بات تمہیں غمگین نہ کرنے پائے (کیو نکہ) غلبہ بکلی اللہ (تعالیٰ)کا(ہی حصہ) الْعَلِيْمُ۰۰۶۶ ہے (اور )و ہ خوب سننے والا( اور) خوب جاننے والا ہے.تفسیر.آپ ؐ کا غم خدا تعالیٰ پر لوگوں کے اعتراضوں کی وجہ سے تھا پہلے تو فرمایا تھا کہ اولیاء اللہ پر غم ہی نہیں آتا.لیکن اب فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ان کی بات غم میں نہ ڈالے.اس کی وجہ وہی ہے جو اوپر بیان ہوچکی ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حزن آپ کا ذاتی نہ تھا بلکہ آپ کا غم خدا تعالیٰ پر اعتراضوں کی وجہ سے تھا.تو فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ان کی بات غم میں نہ ڈالے.عزت تو خدا کی لونڈی ہے.جیسا کہ لِلہِ کے لام سے ثابت ہوتا ہے.کیونکہ لام ملک پر دلالت کرتا ہے.تم کیوں غم کرتے ہو ان کے اعتراض تو فضول ہیں.خدا تعالیٰ کی طرف سے تسلی اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں.ایک طرف تو یہ آیت
Page 155
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے کہ آپ خدا تعالیٰ پر اعتراضوں کی وجہ سے غم کرتے تھے اور دوسری طرف یہ آیت بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ کو کس قدر محبت ہے.کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے سے غم کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی یہ شفقت ہے کہ تسلی دیتا ہے کہ آپ غم نہ کریں وہ سمیع (بہت سننے والا) اور علیم (بہت جاننے والا) ہے جب وہ دیکھے گا کہ ان اعتراضوں سے بد نتیجہ نکلتا ہے اور اس کی عظمت کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ خود ہی ان اعتراضات کو مٹا دے گا.تجھے غم کرنے کی کیا ضرورت ہے.اَلَاۤ اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ١ؕ وَ مَا يَتَّبِعُ سنو! جو (فردِ مخلوق بھی) آسمانوں کے اندر (پایا جاتا) ہے اور جو( بھی) زمین میں (موجود) ہے (ہر ایک) اللہ (تعالیٰ) الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ١ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا ہی کا ہے اور جو لوگ اللہ( تعالیٰ) کے سوا( اور اور چیزوں) کو پکارتے ہیں وہ( دراصل) شریکوں کی پیروی نہیں کرتے الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ۰۰۶۷ (بلکہحق یہ ہے کہ) وہ (اپنے)وہم کے سوا کسی (چیز) کی( بھی )پیروی نہیں کرتے.اور وہ صرف تخمینوں (اور ڈھکونسلوں) سے کام لیتے ہیں.حلّ لُغَات.مَا.أَیُّ شَیْءٍ کے معنی میں بھی آتا ہے.یعنی کیا چیز اور نافیہ ہوکر بھی آتا ہے.یعنی نہیں.پس اس کے ایک معنی یہ ہوئے کہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں.پس لوگ جو خدا تعالیٰ کے سوا اوروں کو پکارتے اور شریک قرار دیتے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سواء اور چیزوں کو پکارنے والے ہیں یہ شرکاء کی اتباع نہیں کرتے.کیونکہ شریک تو کوئی ہے ہی نہیں.یہ تو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں.گویا پہلے معنی کے لحاظ سے ان کے شرکاء کی حقارت کا اظہار ہے اور دوسرے میں نفی کہ ہمارا شریک تو کوئی ہے ہی نہیں.خَرَصَ یَخْرُصُ خَرْصًا.کَذَبَ جھوٹ بولا.خَرَصَ فِیْہِ.حَدَسَ وَقَالَ بِالظَّنِّ ڈھکوسلا مار دیا.یا صرف گمان کی بناء پر ایک بات کہہ دی.یہاں دونوں معنی ہوسکتے ہیں.یہ بھی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ صرف وہموں کی بنا پر بات کرتے ہیں.
Page 156
تفسیر.خدا تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلعم کو تسلی اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح تسلی دلائی ہے.اول یہ کہ جب سزا دینا خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے تو پھر تمہیں حد سے زیادہ غم نہیں ہونا چاہیے.بے شک ان لوگوں کی حالت پر غم کرو.لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھو کہ ان کا فیصلہ ایک قادر خدا کے ہاتھ میں ہے.وہ سزا دینے پر بھی اور اصلاح کرنے پر بھی قادر ہے.دوسرے یہ بتایا ہے کہ جس امر پر یہ لوگ قائم ہیں اس کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں.پس آج نہیں تو کل ان کے مشرکانہ عقائد آپ ہی آپ مٹ جائیں گے.بے حقیقت شی حقیقت کے مقابلہ پر آکر کب تک ٹھہر سکتی ہے.هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَ النَّهَارَ وہ (لا شریک ہستی) وہ (ذات ِپاک) ہے جس نے تمہارے لئے رات کو اس لئے (تاریک) بنایا ہے کہ تم اس میں مُبْصِرًا١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ۰۰۶۸ آرام پاؤ.اور( بالمقابل )دن کو (کام کاج) کے لئے روشن( بنایا ہے) جو لوگ( حق بات کو) سنتے (اور اس سے فائدہ اٹھاتے )ہیں ان کے لئے اس (نظام) میں یقیناً کئی ایک نشان ہیں.حل لغات.سَکَنَ سَکَنَ یَسْکُنُ سُکُوْنًا قَرَّ.ٹھہرا رہا.سَکَنَ فُلَانٌ دَارَہٗ وَسَکَنَ فِیْھَا سَکَنًا وسُکْنًا.اسْتَوْطَنَھَا وَاَقَامَ بِہَا.رہائش اختیار کی.سَکَنَ إِلَیْہِ اِرْتَاحَ راحت پائی.جمعیت خاطر حاصل کی.سَکَنَ عَنْہُ الْوَجَعُ.فَارَقَہٗ درد تھم گیا.دور ہو گیا.(اقرب) مُبْصِرًا مُبْصِرًا اَبْصَرَ سے نکلا ہے جس کے معنی رَاٰہُ کے بھی ہیں.یعنی اسے دیکھا.ا ور جَعَلَہٗ بَصِیْرًا کے بھی ہیں.یعنی اسے دیکھنے والا بنا دیا.(اقرب) اس جگہ دوسرے معنی مراد ہیں.تفسیر.سکون زیادہ قوت کا ذریعہ ہوتا ہے متحرک بالارادہ کا اپنی حرکت کو بند کرنا ہمیشہ مزید طاقت و قوت کے حصول کے لئے ہوتا ہے.درحقیقت تکان کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے بتانے کے لئے پیدا کیا ہے کہ تا مخلوق کو معلوم ہوجائے کہ اب پھر اسے غذا کی ضرورت ہے.جب کسی چیز کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے اندر حرکت سے منافرت پیدا ہوجاتی ہے.اور یہ گویا اس کے لئے ایک تنبیہ ہوتی ہے کہ اب تمہیں غذا لینی چاہیے.اور رات چونکہ کام کے چھوڑنے پر ایک رنگ میں مجبور کردیتی ہے اس لئے وہ گویا باعثِ سکون ہوتی ہے.
Page 157
اس سکون کے ذکر سے مقصود تمثیل ہے رات کا ذکر اس جگہ بطور تمثیل کے لایا گیا ہے.رات انسان کی جسمانی قوتوں کو پھر نشوونما کا موقع دینے کے لئے بنائی گئی ہے.اسی طرح قوموں میں جمود اور جہالت کی حالت ان کے قومی اخلاق کو پھر درست کرنے کا موجب ہوجاتی ہے.اور ایک عرصہ تک باطل رہنے کے بعد پھر اقوام نئے جوش سے اٹھتی ہیں.اسی طرح دن کی تمثیل دی کہ دن بعد میں اس لئے چڑھتا ہے کہ ان حاصل شدہ طاقتوں کو استعمال کیا جائے.پس مخاطبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے کہ اس نکتہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اب جبکہ ان کے لئے دن چڑھایا گیا ہے اپنی حالت کو بدلیں اور سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں.اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس جگہ رات کا ذکر پہلے کیا ہے اور دن کا بعد میں.اگر آنکھوں سے کام نہیں لیتے تو کم از کم کانوں سے ہی سن لو یہاں ایک سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ آخر میں دن کا ذکر تھا.اور اس کے ساتھ مُبْصِرًا فرما کر دیکھنے کی طرف اشارہ فرمایا تھا.پھر باوجود اس کے آیت کواِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ پر کیوں ختم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لفظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ باوجود اس کے کہ تمہارے لئے روحانی سورج چڑھا دیا گیا ہے تم ابھی تاریکی میں پڑے ہوئے ہو اور دیکھنے کے قابل نہیں ہوئے پس کم سے کم کانوں سے تو سن لو تاکہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ہی زندگی پاسکو.قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ١ؕ هُوَ الْغَنِيُّ١ؕ لَهٗ مَا فِي (اور )انہوں نے (تو یہ بھی) کہہ دیا ہے(کہ )اللہ (تعالیٰ) نے (بھی اپنے لئے) اولاد اختیار کی ہے.اس کی تسبیح السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ١ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ (کرو) وہ نہایت (ہی) بے نیازہے.جو کچھ آسمانوں میں (پایا جاتا) ہے اور جو کچھ زمین میں( موجود) ہے بِهٰذَا١ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۰۰۶۹ (سب) اسی کا ہے.اس( دعویٰ) کا تمہارے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے (پھر) کیا تم اللہ (تعالیٰ) کی طرف وہ ( بات) منسوب کرتے ہو جس کی بابت تم( کچھ بھی) علم نہیں رکھتے.حلّ لُغَات.سُلْطَانٌ.اَلسُّلْطَانُ الْحُجَّۃُ دلیلِ محکم.اَلتَّسَلُّطُ.غلبہ، اقتدار.قُدْرَۃُ الْمُلْکِ
Page 158
حکومت.اَلْوَالِیُّ.حاکم اَلْمَلِکُ بادشاہ (اقرب) تفسیر.اتخاذ ولد والےشرک کی تخصیص کے ذکر کی وجہ چونکہ یہ فرمایا تھا کہ کفار کی تباہی کے سامان تو خود اس تعلیم میں پنہاں ہیں جس پر وہ چلتے ہیں.اس لئے اب اس کی وضاحت کے لئے شرک کے عقیدہ کا بطلا ن بھی کر دیا.اور شرک کی اقسام میں سے اس کو چن لیا جو مہذب اقوام میں رائج تھا.اور جس کو سب عقائد سے زیادہ طاقت حاصل تھی یعنی اللہ کے بندہ کو اس کا بیٹا قرار دینا.دوسرے باقی اقسام کے شرکوں میں تو مشرک صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے مگر بیٹا قرار دینے میں ایک چیز کو الوہیت میں شریک قرار دیا جاتا ہے.ابطال عقیدہ اتخاذ ولد اس عقیدے کے رد میں چار دلیلیں پیش کی ہیں.اوّل سُبْحَانَہٗ دوم.ھُوَالغَنِیُّ.سوم لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ.چہارم اِنْ عِنْدَکُمْ مِّنْ سُلْطٰنِ بِہٰذَا.یعنی شرک کی کوئی دلیل نہ ہونا.سُبْحٰنَهٗ کے معنی سُبْحٰنَهٗ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے.اور ولد کا ماننا اس کو عیب میں ملوث قرار دینا ہے.کیونکہ بیٹے کے ہونے کے لئے شہوات کی ضرورت ہے اور یہ عیب ہے.دوم بیٹے کے لئے باپ میں موت کی قابلیت کی شرط ہے اور یہ بھی عیب ہے.ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ نسل انہی چیزوں کی چلتی ہے جو اپنے وقت سے پہلے فنا ہوجاتی ہیں.زمین اور سورج میں سے آگے کوئی اور وجود نہیں نکلتا.کیونکہ ان کی جس عرصہ تک کے لئے ضرورت ہے اس وقت تک وہ قائم رہیں گے.لیکن درخت انسان حیوان چونکہ اس وقت سے پہلے فنا ہوجاتے ہیں جب تک کہ ان کی ضرورت ہے ان کی نسل کا سلسلہ چلتا ہے.تاکہ فنا ہونے والوں کی جگہ دوسرے وجود لے لیں.پس کسی چیز کی نسل کا ہونا اس کے فنا ہونے پر دلالت کرتا ہے.دوسرے سلسلۂ تناسل شہوت پر بھی دلالت کرتا ہے.اور شہوت خود ایک نقص ہے.کیونکہ شہوت جسم کی کسی زیادتی پر دلالت کرتی ہے.جسے جسم میں محفوظ نہ رکھا جاسکے.پس اس سے باہر ایک اور چیز پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.لیکن خدا تعالیٰ سبحان ہے.پس ایسی بات اس کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی.صفت غنا کی دلالت دوسری دلیل یہ دی کہ وہ غنی ہے.کسی کی مدد کا محتاج نہیں.اس لفظ سے ایک دوسری دلیل شرک کے جواز کی رد کردی.اور وہ یہ ہے کہ گو نسل کی اصل غرض فناء کے نقصان کو روکنا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے کاموں میں مدد حاصل کرنے کے لئے اپنی زندگی میں ہی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے.لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے.کسی کی مدد کا محتاج نہیں.پس اس لحاظ سے بھی اس کے ہاں بیٹے کا وجود تسلیم نہیں کیا جاسکتا.
Page 159
صفت مالکیت تیسری دلیل یہ دی کہ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ بعض دفعہ انسان شروع میں کوئی چیز بنا لیتا ہے لیکن بعد میں وہ اس کی طاقت سے نکل جاتی ہے.اور اسے سنبھال نہیں سکتا.لیکن فرمایا کہ اس کو نظام قائم کرنے کے لئے بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں.شرک کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں چوتھی دلیل شرک کے رد میں یہ دی کہ اِنْ عِنْدَکُمْ مِّنْ سُلْطان بِہٰذا.کیا تمہارے پاس شرک کی تائید میں کوئی دلیل ہے ہرگز نہیں.پس اس کا بے دلیل ہونا ثبوت ہے اس بات کا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں.یہ عجیب بات ہے کہ باوجود ہر قسم کا زور مارنے کے شرک کی کوئی دلیل پیدا نہیں ہوسکی.اصولی اور فلسفیانہ بحثیں مشرک کرتے رہتے ہیں.لیکن جن چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں ان کی تائید میں کوئی دلیل پیش نہیں کرسکتے.شرک جہالت کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ والی دلیل کو سورۂ رعد میں اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ۠ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ(الرعد:۳۴) کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے.مگر یہاں پراَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کے الفاظ میں بیان فرمایا اس اختلاف الفاظ کی وجہ یہ ہے کہ اس سورۃ میں تو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ شرک جہالت کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے نہ کہ کسی دلیل کی وجہ سے.اور سورہ رعد میں یہ بتایا ہے کہ شرک کے عقیدہ سے اللہ تعالیٰ پر جہالت کا الزام آتا ہے کہ گویا وہ تو معبودوں کے وجود کا اعلان نہ کرسکا.ان لوگوں نے اپنے علم کے زور سے ان کے خدا ہونے کا پتہ لگا لیا.قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَؕ۰۰۷۰ تو (ان سے) کہہ (کہ )جو (لوگ) اللہ( تعالیٰ) پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتے.مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ (ان کا حصہ) دنیا میں( صرف چند روز کے لئے) کچھ سامان ہے پھر ہماری طرف انہیں لوٹنا ہوگا پھر اس وجہ سے کہ وہ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَؒ۰۰۷۱وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ کفرکرتے (چلے جاتے) ہیں ہم انہیں سخت عذاب کا( مزا) چکھائیں گے.اور تو انہیں نوح کا حال( بھی) سنا.کیونکہ
Page 160
نَبَاَ نُوْحٍ١ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ اس نے (بھی )اپنی قوم سے کہا تھا( کہ) اے میری قوم اگر تمہیں میرا( خداداد) مرتبہ اور اللہ( تعالیٰ) کے نشانوں مَّقَامِيْ وَ تَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ کے ذریعہ سے میرا تمہیں( تمہارا فرض) یاد دلانا ناگوار( گزرتا) ہے تو تم اپنے (تجویز کردہ) شریکوں سمیت اپنی فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ بات (کے متعلق سب پختگی کے سامانوں) کو جمع کر لو( اور) نیز چاہیے کہ تمہاری بات تم پر( کسی پہلو سے) مشتبہ نہ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَيَّ وَ لَا تُنْظِرُوْنِ۰۰۷۲ رہے.پھر اسے مجھ پر نافذ کردو اور مجھے( کوئی موقع اور) مہلت نہ دو.حلّ لُغَات.کَبُرَ کَبُرَعَظُمَ وَثَقُلَ بھاری اور گراں ہوا.کَبُرَ.عَظُمَ وَجَسُمَ بڑا اور جسیم ہوا.(اقرب) عَلَیْہِ الْاَمْرُ شَقَّ وَاشْتَدَّ وَثَقُلَ گراں اور شاق گذرا (منجد) اَلْمَقَامُ.اَلْمَقَامُ اَلْاِقَامَۃُ رہنا بودوباش کرنا.مَوْضِعُ الْاِقَامَۃِ رہنے کی جگہ.زَمَانُ الْاِقَامَۃِ رہنے کا زمانہ یا وقت.مَوْضِعُ الْقَدَمَیْنِ.جہاں پاؤں رکھے جائیں.اَلْمَنْزِلَۃُ مرتبہ و حیثیت (اقرب) اَجْمَعَ اَجْمِعُوْافراء کا قول ہے.اَ جْمَعَ الْاَمْرَ.نَوَاہُ وَعَزَمَ عَلَیْہِ.ارادہ کیا.اور پختہ نیت کرلی.اَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَی الْاَمْرِ.اِتَّفَقُوْا عَلَیْہِ اتفاق کرلیا.اَجْمَعَ اَمْرَہٗ بَعْدَ تَفَرُّقِہٖ جَعَلَہٗ جَمِیْعًا پراگندگی کے بعد جمع کرلیا.اَجْمَعَ الْاَمْرَوَ عَلَی الْاَمْرِ.عَزَمَ.پختہ ارادہ کرلیا (اقرب) غُمَّةٌ غُمَّۃٌ اَمْرٌ غُمَّۃٌ اَےْ مُبْہَمٌ مُلْتَبِسٌ.مبہم اور مشتبہ امر (اقرب) قَضٰی اِلَیْہِ اِقْضُوْا اِلَیکہتے ہیں.قَضَیْنَا اِلَیْہِ ذٰلِکَ الْاَمْرَ.اَبْلَغْنَاہُ اِیَّاہُ اس تک پہنچا دیا.(اقرب) تفسیر.چونکہ سورۂ ہود میں انبیاء کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے اس لئے میں وہیں حضرت نوح کا ذکر کروں گا.ا س جگہ اس آیت کی تشریح پر اکتفا کرتا ہوں میں بتا چکا ہوں کہ الرٰ کی سورتوں میں تاریخی واقعات پر زیادہ بحث ہے.اور انہیں سے زیادہ تر استدلال کیا گیا ہے.چنانچہ عقلی بحث کے بعد حضرت نوح کے واقعہ کو
Page 161
اللہ تعالیٰ پیش فرماتا ہے کہ اس واقعہ پر غور کرکے دیکھ لو.کیا نوح کے دشمنوں نے دشمنی میں کمی کی تھی.مگر باوجود اس کے کہ انہوں نے پورا زور لگایا اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً تباہ نہیں کیا.بلکہ ایک لمبے عرصہ تک ان کو ڈھیل دی.لیکن جب شرارت حد تک پہنچ گئی اور جو ایمان لانے والے تھے ایمان لاچکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک کردیا.یَتْلُوْا.تِلَاوَۃٌ میں سے نکلا ہے.تَلَاوَۃٌ پڑھ کر سنانے کو کہتے ہیں.یعنی لوگوں کی روایات کی طرف مت جاؤ بلکہ وہی سناؤ جو اس کتاب میں اترا ہے.اجمعوا کے دو معنی اس کے مفعول کے مختلف افراد کے مطابق عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بعض دفعہ فعل ایک ہی لایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دو اسم استعمال کرکے ان ہر دو اسموں کے مناسب حال اس کے دو معنی لئے جاتے ہیں.ا س جگہ اَجْمِعُوْا شُرَکَاءَکُمْ کے یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ ان کو جمع کرلو.اور یہ بھی کہ تم اپنے معاملہ کو جمع کرلو اور اپنے شرکاء کو بلالو.اور اُدْعُوْا کا فعل حذف کر دیا گیا ہے.ایک شاعر کہتا ہے یَالَیْتَ زَوْجَکِ قَدْغَدَا مُتَقَلِّدًا سَیْفًا وَرُمْحَا (تاج العروس،مادہ جمع) جس میں سَیف (تلوار) اور رُمْحٌ (نیزہ) ہر دو کے لئے تَقَلُّد کا لفظ لایا گیا ہے.حالانکہ یہ سیف کے لئے مخصوص ہوتا ہے اور رمح کے لئے تقلد کا نہیں بلکہ اعتقال کا لفظ بولا جاتا ہے.تین مثالوں سے مقصود تین قسم کے معاملہ کی طرف اشارہ ہے اس سورۃ میں تین مثالیں دی ہیں.ایک حضرت نوح ؑ کی.دوسری حضرت موسیٰ ؑ کی اور تیسری حضرت یونس ؑ کی.حضرت نوح کی مثال کامل تباہی کی ہے.اور حضرت موسیٰ ؑ کی مثال ایک قوم کی تباہی اور دوسری کی نجات کی.اور حضرت یونسؑ کی مثال کامل طور سے بچا لینے کی ہے.اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تین مثالیں بیان فرما کر بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں تین قسم کے معاملات کیا کرتے ہیں.حضرت نوح ؑ کی قوم کی خصوصیت(۱) کسی نبی کے ذریعہ سے مخالف قوم کو بالکل تباہ کردیتے ہیں.جیسے حضرت نوح کی قوم ہے.ان کے زمانہ میں بجز چند نفوس کے باقی تمام قوم ہلاک کر دی گئی.حضرت موسیٰ ؑکی قوم کی خصوصیت اور کسی نبی کے زمانہ میں اس کے مخاطبین میں سے ایک حصے کو بچا لیتے اور دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں.جیسے حضرت موسیٰ ؑ کے مخاطبین کا حال ہوا کہ بنی اسرائیل اکثر ان پر ایمان لے آئے مگر فرعون اور اس کی قوم تبہ ہو گئی.حضرت یونسؑ کی قوم کی خصوصیت اور اس کے نمونہ سے فائدہ اٹھانے کی تحریص اور کسی نبی کے
Page 162
زمانہ میں کلی طور پر بچا لیا کرتے ہیں.جیسے حضرت یونسؑ کی قوم جو ساری کی ساری بچا لی گئی تھی ان مثالوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو تحریص دلائی ہے کہ کیوں تم یونسؑ کی سی قوم نہیں بن جاتے.موسیٰ ؑ اور نوح کی قوموں کی طرح کیوں تباہی چاہتے ہو؟ ان تمام خصوصیات کا آنحضرت ؐ کی قوم میں پایا جانا عا م طور پر لوگ نبیوں کے واقعات کو قرآن مجید میں محض قصہ سمجھتے ہیں.مگر ان تینوں واقعات کے نظام اور ان کی ترتیب پر غور کرو.کیا یہ محض قصہ کے طور پر ذکر کئے گئے ہیں.کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف زمانوں میں اور مختلف جگہوں میں یہی واقعات پیش نہیں آئے.کیا آپ مکہ میں نوح، مدینہ میں موسیٰ اور دوبارہ ورود مکہ میں یونس کے مثیل ثابت نہیں ہوئے ہیں؟ یہ قصے نہیں بلکہ پیشگوئیاں ہیں.نبی کا مقام اور اس کی تذکیر اس کی قوم پر گراں گزرنے کی وجہ مَقَامِیْ وَتَذْکِیْرِیْ میں حضرت نوح ؑ نے بتلایا ہے کہ میری دو باتیں ہی تمہیں بری لگ سکتی ہیں.اول میرا نبی ہونا جس سے تم کو یہ خیال ہوگا کہ یہ ہم پر کیوں حاکم ہو گیا؟ کیونکہ نبی کو بھی ایک قسم کی حکومت تو حاصل ہوتی ہی ہے.دوم میری تعلیم.کیونکہ یہ تعلیم تمہارے طرز کے خلاف ہے.حضرت نوح کا جواب فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو باتیں تمہیں بری لگتی ہیں تو میں تمہیں ان دونوں کے متعلق یقین دلاتا ہوں کہ انہیں میرے نفس نے خود پیدا نہیں کیا.بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اس میں میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے.میں نے تو اپنے سب کام اللہ کے سپرد کردیئے ہیں.یعنی میری اپنی خواہش کوئی نہیں.جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے.اس لئے یقین رکھو کہ تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہے.لفظ مقام کے دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہمَقَامِیْ وَتَذْکِیْرِیْ کو اکٹھا سمجھا جائے.اور یہ معنی کئے جائیں کہ اگر میرا کھڑے ہوکر وعظ کرنا تم کو برا معلوم ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ میں تو اس طریق کو نہیں چھوڑ سکتا.کیونکہ یہ میرا فرض ہے.اور اگر اس کے نتیجہ میں تم مجھ سے دشمنی کروگے تو بے شک کرو.میں خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں.کھڑے ہو کر تذکیر کر نا انبیاء کی سنت ہے ان معنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم سے انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ کھڑے ہوکر وعظ فرمایا کرتے تھے.ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ کھڑے ہوکر ہی فرماتے تھے(بخاری کتاب الجمعۃ باب الخطبۃ قائمًا).حضرت مسیح موعود بھی سوائے بیماری کے کھڑے ہوکر ہی عموماً لیکچر دیاکرتے تھے.
Page 163
کامل تدبیر کے پانچ طریق اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کامل تدبیر کس طرح کی جاتی ہے.اور اس کے لئے پانچ طریق بتائے.(۱) مشورہ کرکے ایک رائے پر جمع ہوجانا چاہیے.جب تک کوئی قوم ایسا نہ کرے گی وہ کبھی جیت نہیں سکتی.(۲) اپنے ہم خیال لوگوں کو ایک نظام کے ماتحت لے آنا چاہیے.(۳) اس رائے کے پورا کرنے کے لئے ایک تفصیلی تجویز سوچ لینی چاہیے.یا دوسرے لفظوں میں تفصیلی نقشہ تیار کرلینا چاہیے.(۴) بغیر انتشار طاقت کے ایک ہی وقت میں سب طاقت کو خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ساری قوم کا زور ایک ہی وقت میں دشمن پر پڑے.(۵) حملہ کرنے کے بعد دشمن کو سانس لینے کا بھی موقع نہ دینا چاہیے کیونکہ اس صورت میں دشمن پھر طاقت پیدا کرلے گا.پہلا حملہ ختم نہ ہونے پائے کہ دوسرا شروع ہوجائے.تمام انبیاء اسی طریق پر کاربند ہوتے چلے آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہی طریق تھا.آپ ایک اشتہار نکالتے ابھی اس کا چرچا جاری ہوتا کہ دوسرا اور نکال دیتے تھے.غرض کامیابی کے لئے یہ پانچ طریق ضروری ہوتے ہیں.حضرت نوحؑ اپنی قوم کو خود ان طریقوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں تم یہ پانچوں طریق استعمال کرلو.مگر پھر بھی کامیاب نہ ہوگے.کیونکہ ایک چھٹی چیز جس کے بغیر یہ تمام تدبیریں ناکام رہ جاتی ہیں یعنی توکل علی اللہ وہ تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ وہ میرے پاس ہے.اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی مدد مجھے حاصل ہے.پس تم تمام کوششیں کرلو.غالب میں ہی رہوں گا.انبیاء کا یقین اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر انبیاء ؑ کو اپنی صداقت اور خدا تعالیٰ کے وعدوں پر کیسا یقین ہوتا ہے.نہ صرف یہ کہ وہ مخالفین کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ انہیں اور بھی غیرت دلاتے ہیں.اور باوجود اس کے مطمئن ہوتے ہیں کہ آخر ہم ہی جیت کر رہیں گے.اور آخر ویسا ہی ہوتا ہے.دوسرے معجزات کو نظرانداز کرکے چشم حقیقت بین کے لئے یہی ایک معجزہ ان کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے ثبوت میں کافی ہوتا ہے مگر افسوس کہ اندھی دنیا دیکھتی نہیں.
Page 164
فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ١ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا پھر( بھی) اگر تم پھر جاؤ تو( اس میں میرا کوئی نقصان نہیں.بلکہ تمہارا ہی ہے )کیونکہ میں نے تم سے (اس کی بابت) کوئی اجر عَلَى اللّٰهِ١ۙ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۰۰۷۳ نہیں مانگا.میرا اجر اللہ( تعالیٰ) کے سوا( اور) کسی پر نہیں ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں (اس کے) کامل فرمانبرداروں میں سے بنوں.تفسیر.انبیاء کے دشمن اعتراض کیا کرتے ہیں کہ وہ حکومت پسند ہوتے ہیں.اور لوگوں پر غلبہ حاصل کرنا ان کا فطرتی تقاضا ہوتا ہے.اس آیت میں اس اعتراض کا خوب قلع قمع کیا گیا ہے.انبیاء کی زندگی اطاعت اور فرمانبرداری کی ایک بہترین مثال ہوتی ہے.اگر وہ حکومت کے خیال سے سب کچھ کرتے ہوتے تو لوگوں پر حکومت کرتے اور خود اپنے نفس کو تکلیف میں نہ ڈالتے مگر وہ تو خود اپنے نفس کو سب سے زیادہ تکلیف میں ڈالتے ہیں.وہ لوگوں کو ہی عبادت کا حکم نہیں دیتے بلکہ سب سے زیادہ خود عبادت کرتے ہیں.دوسروں کو ہی زکوٰۃ کا حکم نہیں دیتے بلکہ خود سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کی خواہش ان پر غالب نہیں ہوتی.بلکہ اطاعت و فرمانبرداری کی صفت ان پر غالب ہوتی ہے.اور وہ اول المسلمین ہوتے ہیں.یعنی فرمانبرداروں کے سردار.حکومت پسندی اور فرمانبرداری دو متضاد باتیں ہیں ممکن ہے کسی کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ بعض بڑے بڑے جابر بادشاہ گذرے ہیں.جو بڑے عابد اور صدقہ و خیرات بھی کرنے والے تھے.لیکن یہ اعتراض درست نہیں.بے شک ایسے لوگ بھی ہوسکتے ہیں.جو جابر بھی ہوں اور عبادت گزار بھی ہوں.مگر ایسے لوگ وہی ہوں گے جن کا ایمان ورثہ کا ایمان ہوگا.جو شخص اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ کہتے ہوئے نئے سرے سے اپنی قوم میں نیکی اور تقویٰ کی عادت ڈالتا ہے اس میں کبھی یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوسکتیں.کیونکہ اس کے اندر دونوں باتیں اسی کے نفس سے پیدا ہونی ضروری ہیں.اور یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کے دل میں ایک ہی وقت میں لوگوں پر حکومت کرنے کا خیال بھی پیدا ہو اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اور کرانے کا بھی.ہاں یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص کو اس کے ماں باپ یا بزرگ عبادت کی عادت ڈال دیں اور اپنی طبیعت کی رو سے وہ جابر اور ظالم بھی ہو.
Page 165
پس گو ورثہ کے ایمان والا ان متضاد باتوں کو جمع کرسکتا ہے.مگر مذہب کا بانی ایسا نہیں کرسکتا.فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍمیں حضرت نوحؑ کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ اگر تم نے پیٹھ پھیری اور جیسا کہ پیشگوئی سے ظاہر ہے تم ضرور پیٹھ پھیرو گے اور میں تم پر غالب آیا.تب بھی میں کوئی مالی ذمہ داری تم پر نہیں ڈالوں گا.کیونکہ میں نے یہ کام تمہاری خیرخواہی کے لئے کیا ہے نہ پہلے کوئی اجر مانگا نہ آئندہ کوئی اجر اپنے لئے وصول کروں گا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملہ میں اسوہ اگرچہ حضرت نوح ؑ کو یہ موقع نہیں ملا کہ دشمن ان کے مقابلہ میں حملہ کرکے شکست کھاگئے ہوں اور پھر حضرت نوح ؑ کو ان سے فاتحانہ معاملہ پڑا ہو اور پھر انہوں نے کچھ نہ لیا ہو.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا.آپ کی قوم آپ کے ہاتھوں مفتوح ہوئی اور حضور فاتحانہ طریق سے داخل مکہ ہوئے.اور حضور نے ان سے اس حالت میں بھی اپنے نفس کے لئے ایک حبہ بھی وصول نہ کیا.اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مجھے تو خدمت ہی کا حکم ہے.بادشاہت کے لئے تو میں بنایا ہی نہیں گیا.پس اگر میں غالب بھی آ گیا تب بھی میرا کام خدمت کرنا ہی ہوگا.سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ع منہ از بہرِ ماکرسی کہ ماموریم خدمت را (آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۵۵) فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْنٰهُمْ (مگر) پھر( بھی) انہوں نے اسے جھٹلایا.تب ہم نے اسے اور( نیز) انہیں جو کشتی میں اس کے ساتھ (سوار) تھے خَلٰٓىِٕفَ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا١ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ بچالیا اور انہیںہم نے جانشین بنا دیا اور جن لوگوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا( تھا) انہیں ہم نے غرق کر دیا.كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ۰۰۷۴ سودیکھ (کہ )جن لوگوں کو(اس عذاب سے) آگاہ کر دیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا.حلّ لُغَات.خَلِیْفَۃٌ خَلَائِفُکا واحد خلیفۃ ہے.اَلْخَلِیْفَۃُ مَنْ یَّخْلُفُ غَیْرَہٗ وَیَقُوْمُ مَقَامَہٗ
Page 166
جانشین اور قائم مقام.اَلسُّلْطَانُ الْاَعْظَمُ.حاکم اعلیٰ.شاہنشاہ.اَلْاِمَامُ الَّذِیْ لَیْسَ فَوْقَہٗ اِمَامٌ وہ پیشرو اور حاکم جس کے اوپر اور کوئی حاکم اور پیشرو نہ ہو.(اقرب) تفسیر.آخری حصہ آیت سے یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کی سزا میں کہ جن کو پہلے متنبہ نہ کیا گیا ہو اور ان لوگوں کی سزا میں جنہیں متنبہ کر دیا گیا ہو فرق ہوتا ہے.تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ جن لوگوں کو متنبہ کر دیا گیا تھا ان کی سزا کیسی تھی.یعنی عام لوگوں کی سزا اور ان لوگوں کی سزا میں ایک بین فرق تھا.اس آیت میں انبیاء اللہ اور رسولوں کے درجہ کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے وجود ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے.ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ پھر اس کے بعد ہم نے اور( بھی کئی) رسول اپنی (اپنی) قوم کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس روشن نشانات لے کر بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ١ؕ آئے تو وہ (لوگ) اس سبب سے کہ( اس سے) پہلے اس (صداقت) کو جھٹلا چکے تھے (اس پر) ایمان لانے والے كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ۰۰۷۵ نہ بنے.ہم حد سےبڑھنے والوں کے دلوں پر اسی طرح سے مہر لگایا کرتے ہیں.حلّ لُغَات.طَبَعَ طَبَعَ الشَّیْءَ صَوَّرَہٗ بِصُوْرَۃٍ مَّا اس کی کوئی صورت یا شکل بنائی.عَلَیْہِ خَتَمَ مہر لگائی.اَللہُ الْخَلْقَ خَلَقَہُمْ پیدا کیا.اَلسَّیْفَ عَمِلَہٗ وَصَاغُہٗ بنایا.اَلدِّرْھَمُ نَقَشَہٗ وَسَکَّہٗ مضروب کیا.(اقرب) تفسیر.دلوں پر مہر لگانے کے معنی اس آیت میں مہر لگانے کی حقیقت کو اچھی طرح کھول دیا ہے اور دلوں پر مہر لگانے پر دشمنانِ اسلام جو اعتراض کیا کرتے ہیں اس کا بوضاحت جواب دے دیا گیا ہے.فرماتا ہے کہ چونکہ کفار پہلے انکار کر چکے تھے اس واسطے ایمان لانا ان کے لئے مشکل ہو گیا.اور اپنے اقوال اور اعمال کی پچ کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہلنے سے انہوں نے انکار کر دیا.پھر فرماتا ہے كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ.ہم جو کہا کرتے ہیں کہ حدود کو توڑنے والوں کے دلوں پر ہم نے مہر لگادی ہے اس کا یہی مطلب ہوا کرتا ہے کہ چونکہ وہ ضد
Page 167
کرتے ہیں ہم انہیں ہدایت نہیں دیتے نہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے انہیں ہدایت سے روکتے ہیں.پس وہ مہر اصل میں بندہ کی طرف سے ہوتی ہے گو بوجہ اس کے کہ نتائج خدا تعالیٰ مرتب فرماتا ہے.اسے منسوب خدا تعالیٰ کی طرف کر دیا جاتا ہے.ایک دوسری جگہ فرماتا ہے اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا (محمد :۲۵) کہ جو تالے کفار کے دلوں پر لگے ہوئے ہیں وہ خود ان کے دلوں سے ہی پیدا شدہ ہیں.ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَ هٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے نشان دے کر فرعون اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کی طرف بھیجا.مَلَاۡىِٕهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا۠ وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ۰۰۷۶ تو انہوں نے تکبر (اختیار) کیا اور وہ (پہلے ہی سے) ایک مجرم قوم تھے.حلّ لُغَات.اَلْمَلَأُ.اَلْمَلَأُ مَلَأَ یَمْلَأُ سے نکلا ہے.جس کے معنی بھر دینے کے ہوتے ہیں.اَلْمَلَأُ کے معنی ہیں.اَلْاَشْرَافُ.وَسُمُّوْالاَنَّھُمْ یَمْلَئُوْنَ الْعُیُوْنَ اُبَّھَةً وَالصُّدُوْرَ ھَیْبَۃً.معزز لوگ اور ان کا نام مَلَأٌ اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ آنکھوں کو عظمت سے اور سینوں کو ہیبت سے بھر دیتے ہیں.اَلْجَمَاعَۃُ جماعت.اَلتَشَاوُرُ باہم مشورہ کرنا.چنانچہ کہتے ہیں مَاکَانَ ھَذَاالْاَمْرُ عَنْ مَلَأ ٍمِّنَّا.اَیْ تَشَاوُرٍ.ہمارے مشورہ سے یہ بات نہیں ہوئی.(اقرب )اِسْتَکْبَرَ الرَّجُلُ کَانَ ذَاکِبْرِیَاءَ.بڑا بنا.مغرور ہوا.(اقرب) تفسیر.لوگوں کے انکار انبیاء کے دو باعث جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتا ہے تو لوگ دو وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں.یا تو اس کے دعویٰ کو بڑا خیال کرتے ہیں اور یا اپنے آپ کو اس امر سے بالا سمجھتے ہیں کہ اس کی بات مان لیں.یہی حال حضرت موسیٰ ؑ کا ہوا.بعض نے یہ بات ناممکن سمجھی کہ خدا تعالیٰ بندہ سے کلام کرے اور بعض نے یہ بات خلاف شان سمجھی.کہ موسیٰ ؑ جیسے بے کس انسان کی اطاعت کریں.كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ کے دو معنی وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ کے دو معنی ہوسکتے ہیں (۱) وہ پہلے ہی سے مجرم تھے.اس لئے حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا.ان معنوں کے رو سے اِسْتَکْبَرُوْا کی وجہ معلوم ہوجاتی ہے.کہ اس لئے نہ مانا کہ اس طرح ان کی آزادی میں فرق آتا تھا.اور برے کاموں میں روک پیدا ہوتی تھی.(۲) دوسرے معنی اس کے یہ ہوسکتے ہیں کہ وہ انکار کرکے مجرم بن گئے.صداقت کے انکار کے ساتھ ان دونوں معنوں کا تعلق ہے.
Page 168
بدی بدی کی طرف مائل کرتی ہے.پس یہ بھی سچ ہے کہ جو لوگ مجرم ہوتے ہیں وہ صداقت کے قبول کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں.اور یہ بھی سچ ہے کہ صداقت کا انکار کرکے انسان کے تقویٰ کو سخت صدمہ پہنچتا ہے.اور اگر پہلے اس شخص میں خشیت الٰہی ہوتی بھی ہے تو صداقت کے انکار کے بعد یکدم یا آہستگی سے جاتی رہتی ہے.پس صداقت کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں.جو شخص تقویٰ کی کچھ بھی قدر کرتا ہو اسے اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے.فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا( کہ) یہ یقیناً یقیناً ایک (تعلقات کو) کاٹ لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ۰۰۷۷ دینے والا فریب ہے.حلّ لُغَات.اَبَانَ.مُبِیْنٌ اَبَانَ سے ہے.اس کے معنی ہیں فَصَلَ جدا کیا.الشَّیْءَ اِتَّضَحَ واضح ہوا.اَلشَّیْءَ اَوْضَحَ.واضح کیا.(اقرب) تفسیر.جب کبھی کوئی سچائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو لوگ اسے سِحْرٌ مُبِیْنٌ کہہ دیتے ہیں.اور ان دو لفظوں میں شرارت کی ساری صورتیں مخفی ہیں.دنیا میں ہمیشہ دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں.مذہبی اور سیاسی.سِحْرٌ یعنی فریب کہہ کر ان لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے جو مذہبی ہوتے ہیں.انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ یہ فریب ملک کے مذہب کو بگاڑ دے گا.اور مُبِیْنٌ کہہ کر سیاسی لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک فریب نہیں بلکہ قوم میں تفرقہ ڈال دینے والا فریب ہے.پس اگر قوم کی خیرخواہی مدنظر ہے تو اس کا مقابلہ کرو.ورنہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی.جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے.یہ شیطانی حربہ برابر استعمال ہو رہا ہے اور ابھی تک بیکار نہیں ہوا.اس زمانہ کے مصلح کے مقابلہ میں بھی یہی حربہ استعمال کیا گیا.اور کیا جارہا ہے.اور لوگ ہیں کہ قرآن کریم میں ان سب امور کو پڑھتے ہوئے غور اور تدبر سے کام نہیں لیتے اور نہیں سوچتے کہ قوم تو پہلے ہی سے مٹ چکی تھی.تفرقہ کس میں ڈالنا تھا.اگر بنانا ہی تفرقہ ہوتا ہے تو تفرقہ نہ معلوم کسے کہتے ہیں؟
Page 169
قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ١ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا١ؕ (اس پر) موسیٰ نے (ان سے )کہا( کہ) کیا تم حق کی نسبت (ایسا )کہتے ہو (اور وہ بھی اس وقت) جبکہ وہ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ۰۰۷۸ تمہارے پاس آگیا ہے کیا یہ فریب (ہو سکتا )ہے حالانکہ فریب دینے والے کامیاب نہیں ہوتے.تفسیر.اَسِحْرٌ هٰذَا.یعنی یہ تعلیم تمہارے سامنے موجود ہے.اس کا اثر بھی نمایاں ہے.اس کی تفصیلات بھی تم جان چکے ہو.کیا پھر بھی تم اس کو سحر قرار دیتے ہو؟ یہ تو جھوٹ کا سر کچلنے والی کتاب ہے.یہ سحر کس طرح ہوسکتی ہے.فریبی شخص انبیاءکے مقاصد کو نہیں پا سکتا وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ فریب کی باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں وہ نبیوں کے مقاصد کو حاصل نہیں کرسکتے.پس میں اگر ساحر ہوں تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا.نبیوں کا مقصد قوم کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور سیاسی حالت کو بدل ڈالنا ہوتا ہے.خواہ جلد خواہ بدیر.کوئی نبی اس مقصد کے بغیر نہیں آتا.حضرت موسیٰ ؑ کہتے ہیں کہ میں ان مقاصد کو پورا کررہا ہوں.اور ایک دن پورے طور پر پورا کرکے دکھا دوں گا.پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ جو شخص یہ تغیرات پیدا کردے وہ فریبی اور جھوٹا ہے؟ قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَ تَكُوْنَ انہوں نے کہا کیا تو (اس لئے) ہمارے پاس آیا ہےکہ جس بات پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس سے لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْاَرْضِ١ؕ وَ مَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ۰۰۷۹ ہمیں ہٹا دے.اور تم( دونوں) کو ملک میں بڑائی حاصل ہو جائے.اور ہم( تو) تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے.حلّ لُغَات.لَفَتَ لِتَلْفِتَنَا لَفَتَ الشَّیْءَ یَلْفِتُ لَفْتًا لَوَاہُ وَصَرَفَہٗ اِلَی ذَاتِ الْیَمِیْنِ وَالشَّمَالِ پھیر دیا.اور دائیں بائیں کر دیا.فُلَانًا عَنْ رَأْیِہٖ اَیْ صَرَفَہٗ عَنْ رَأْیِہٖ.رائے بدلوا دی.(اقرب) اَلْکِبْرِیَاءُ اَلْکِبْرِیَاءُ الْعَظْمَۃُ.بڑائی وَالتَّجَبُّرُ.جبر سے کام لینا.چیرہ دستی وَفِی اللِّسَانِ اَلْعَظْمَۃُ وَالْمُلْکُ.لسان العرب میں ہے کہ اس کے معنی بڑائی اور حکومت کے ہیں.وَقِیْلَ ھِیَ عِبَارَۃٌ عَنْ کَمَالِ
Page 170
الذَّاتِ وَکَمَالِ الْوَجُوْدِ وَلَا یُوْصَفُ بِہَا اِلَّا اللہُ تَعَالٰی.اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ذاتی کمال کے ہیں.اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو اس لفظ سے موصوف نہیں کیا جاسکتا.گویا جب بندے کے لئے یہ لفظ آتا ہے تو ہمیشہ برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.یعنی تجبر کے معنوں میں.فِی الْاَرْضِ.اس ملک میں نہ یہ کہ ساری دنیا میں.تفسیر.سحر مبین میں دو اعتراض سِحْرٌ مُّبِيْنٌ میں جو دو اعتراض مختصر الفاظ میں بتائے گئے تھے اس آیت میں ان کی تشریح کر دی گئی ہے.پہلے حصۂ آیت میں کفار کے سرداروں کا یہ اعتراض نقل کیا گیا ہے کہ یہ شخص ہمیں باپ دادا کی تعلیم سے پھرانا چاہتا ہے.اور اکثر لوگوں کے نزدیک وہی حق ہوتا ہے جس پر کہ ان کے باپ دادے چلتے آئے ہوں.پس دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ شخص ہمیں حق سے پھرانا چاہتا ہے.مگر اس مضمون کو ایسے رنگ میں بیان کیا ہے کہ عوام الناس میں خوب جوش پھیل جائے.دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ شخص تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے.اسے اس آیت میں ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے کہ موسیٰ اور ہارون حکومت چاہتے ہیں.اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہوا کرتا ہے کہ موجودہ نظام سے تعلق رکھنے والے افراد میں تفرقہ ڈلوا دیا جائے.وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ۰۰۸۰ اور فرعون نے (اپنے لوگوں سے) کہا (کہ) تم میرے پاس( ملک بھر کے) ہر ایک کامل واقفیت والے ساحر کو لے آؤ.تفسیر.ایک غلطی سے دوسری غلطی کا ارتکاب دیکھو ایک غلطی سے انسان کس طرح دوسری غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے.خدا کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا تو نتیجہ یہ نکلا کہ خود بھی علمی تحقیق سے محروم رہ گئے.اور اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس گئے.ساحر کہا تو ان کے مقابلہ کے لئے ساحروں ہی کی تلاش ہوئی.فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ۰۰۸۱ پس جب ساحر( لوگ) آئے تو موسیٰ نے انہیں کہا( کہ) جو کچھ تمہیںڈالنا ہے ڈالو.تفسیر.حضرت موسیٰ کا استغناء جب جادوگر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ
Page 171
جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو.یعنی جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو.میں تو اسے فضول سمجھتا ہوں.گویا اظہار استغناء فرمارہے ہیں.لوگ اس آیت کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بھی ان کے مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے.حالانکہ یہ بات نہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوب معلوم تھا کہ وہ جادوگر ہیں اور جو کچھ کریں گے وہ فضول ہی ہوگا.انہوں نے تو استغناء کا اظہار کیا ہے.موسیٰ ؑ نے فوراً ہی انکار غالباً اس لئے نہیں کیا کہ انہوں نے سوچا کہ جب وہ مقابل پر آئیں گے تو حقیقت خود ہی آشکار ہو جائے گی.اور اسی وقت کہنا مناسب بھی ہوگا.چنانچہ وقت پر یہ کہہ دیا کہ مَاجِئْتُمْ بِہِ السِّحْرُ.فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ١ۙ السِّحْرُ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ اس پر جب انہوں نے (جو کچھ ڈالنا تھا )ڈال دیا تو موسیٰ ؑنے کہا( کہ) جو کچھ تم( لوگوں) نے پیش کیا ہے( پورا) پورا سَيُبْطِلُهٗ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ۰۰۸۲ فریب ہے (اور)اللہ (تعالیٰ) یقیناًیقیناً اسے مٹادے گا اللہ (تعالیٰ) فساد کر نے والوں کی کارروائی کو درست ہرگز نہیں (کیا )کرتا.حلّ لُغَات.اَصْلَحَہٗ اَصْلَحَہٗ ضِدُّ اَفْسَدَہٗ ٹھیک کر دیا.درست کر دیا.مناسب حال کر دیا.بَعْدَ فَسَادِہٖ اَقَامَہٗ خرابی کو دور کرکے درست کر دیا.بَیْنَ الْقَوْمِ وَفَّقَ صلح کروائی.اِلَیْہِ اَحْسَنَ احسان کیا.اِلَی دَآبَّتِہٖ اَحْسَنَ اِلَیْہَاوَ تَعَہَّدَھَا.اسے اچھی طرح سے رکھا اور اس کا پورا خیال رکھا.اَصْلَحَ اللہُ لَہٗ فِی ذُرِّیَتِہٖ وَمَالِہٖ.اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد اور مال کی بہتری اور درست حالی نصیب کی.(اقرب) تفسیر.مفسدوں کے اعمال کا نتیجہ جھوٹ اور فریب جب صداقت کے مقابلہ پر آتا ہے تو اس کا پول کھل جاتا ہے اور مفسدوں کے اعمال فساد ہی پیدا کرتے ہیں.یہ نہیں ہوسکتا ہے کہ کرے تو انسان مفسدوں والے اعمال اور نتیجہ اصلاح نکلے.تو بتایا کہ وہ مفسدین کے ارادوں اور ان کے عملوں کو آپس میں مناسب حال نہیں ہونے دیتا.بلکہ وہ اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں.اور اس وجہ سے انہیں کامیابی بھی نصیب نہیں ہوتی.
Page 172
وَ يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَؒ۰۰۸۳ اور اللہ( تعالیٰ) اپنے کلمات کے ذریعہ سے حق کو قائم کرتا ہے.گو مجرم( لوگ اس بات کو) ناپسند کریں.تفسیر.کلمات میں بشارتیں اور انذار دونوں شامل ہیں.ان دونوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کیا کرتا ہے.حق کو باطل کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ ایک عجیب لطیفہ بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت کے لئے جھوٹ اور فریب کا محتاج نہیں.ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے.وہ اپنے حکم سے دین کی اشاعت کرتا ہے نہ کہ بندے کے فریب سے.اس میں یہ اخلاقی نکتہ ہے کہ مقصد کی سچائی ہمیں اس بات کا مجاز نہیں بنادیتی کہ ہم اس کے حصول کے لئے جھوٹے ذرائع اختیار کریں.مقصد خواہ کتنا ہی اعلیٰ ہو ذرائع حصول بھی اعلیٰ ہونے چاہئیں.افسوس ہے کہ اس زمانہ میں بہت سے لوگ اس صداقت سے نابلد ہورہے ہیں.اور عام طور پر دنیا میں یہ وباء پھیل رہی ہے کہ سچائی کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے.حالانکہ وہ سچائی ہی کیا جو جھوٹ کے بغیر غالب نہ آسکے! فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ پھر( بھی) سوائے اس کی قوم( ہی) کےچند بچوں کے کسی نے (بھی )فرعون (کے ڈر سے) اور (نیز) اپنی قوم کے فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡىِٕهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ١ؕ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ بڑے لوگوں کے خوف سے کہ وہ( خود ہی یا دوسروں کےذریعہ سے )انہیں(کسی) مصیبت میں( نہ) ڈال دے فِي الْاَرْضِ١ۚ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ۰۰۸۴ موسیٰ کی فرمانبرداری نہ( اختیار)کی اور فرعون یقینا ًیقیناً زمین میں چیرہ دستی کرنے والاتھا اور یقینا ً یقیناً وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا.حلّ لُغَات.اٰمَنَ اٰمَنَہٗ اٰمَنَ.امن بخشا.بچایا اٰمَنَ بِہٖ صَدَّقَہٗ وَوَثَقَ بِہٖ.ایمان لایا.تصدیق کی
Page 173
اور پورا اعتماد کیا.اٰمَنَ لَہٗ خَضَعَ وَاِنْقَادَ.فرمانبرداری اختیار کی.مطیع ہو گیا.کہنا مان لیا.(اقرب) ذُرِّیَۃٌ اَلذُرِّیَۃُاَلصِّغَارُ مِنَ الْاَوْلَادِ وَاِنْ کَانَ قَدْ یَقَعُ عَلَی الصِّغَارِ وَالْکِبَارِ مَعًا فِی التَّعَارُفِ.یعنی ذُرِّیَۃ کے معنی چھوٹی عمر کے بچوں کے ہوتے ہیں.لیکن کبھی عرف عام میں چھوٹے اور بڑے سب بچوں کے لئے مشترک طور پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے.وَیُسْتَعْمَلُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَاَصْلُہٗ لِلْجَمْعِ.اور یہ لفظ ایک بچہ کے لئے بھی اور زیادہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے.گو اصل میں جمع کے لئے ہی یہ لفظ بنا ہے.(مفردات) علا کے معنی علاوہ اور معانی کے (تعلیل) یعنی اظہار سبب و علت کے بھی ہوتے ہیں.(اقرب) فَتَنَ.فَتَنَ یَفْتِنُ فَتْنًا وَفُتُوْنًا.اَعْـجَبَہٗ اسے پسند آیا.فَتَنَ الْمَالُ النَّاسَ.اِسْتَمَالَھُمْ مال نے ان کو اپنی طرف مائل کیا.فَتَنَتِ الْمَرْأَۃُ فُلَانًا وَلَّھَتْہُ اس عورت نے اس مرد کو اپنا فریفتہ بنالیا.فَتَنَ زَیْدٌ عَمْرًا اَوْقَعَہٗ فِی الْفِتْنَۃِ فَفَتَنَ اَیْ فَوَقَعَ.زید نے عمرو کو فتنہ میں ڈال دیا اور وہ فتنہ میں پڑ گیا.یعنی لازم و متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے.فُلَانًا فِتْنَۃً وَمَفْتُوْنًا اَضَلَّہٗ اسے گمراہ کر دیا.فَتَنَ الرَّجُلُ فَتْنًا اِلَی النِّسَآءِ.اَرَادَ بِہِنَّ الْفُجُوْرَ.عورتوں سے بدکاری کا ارادہ کیا.فَتَنَ الشَّیْءَ فَتْنًا.اَحْرَقَہٗ اس چیز کو جلا دیا.اور انہی معنوں میں قرآن کریم کی اس آیت میں یہ لفظ آیا ہے.وَھُمْ عَلَی النَّارِ یُفْتَنُوْنَ (اقرب) فَتَنَ فُلَانًا عَنْ رَأْیِہٖ.صَدَّہٗ اس کو اس کی رائے سے باز رکھا.فَتَنَ الصَّائِغُ الذَّھَبَ وَالْفِضَّۃَ فِتْنَۃً اَذَابَہٗ بِالْبُوْتَقَۃِ وَاَحْرَقَہٗ بِالنَّارِ لِیُبَیِّنَ الْجَیِّدَ مِنَ الرَّدِیِّ وَیُعْلَمُ اَنَّہُ خَالِصٌ اَوْ مَشُوْبٌ وَھُوَ اَصْلُ مَعْنَی الْفِتْنَۃِ.یعنی چاندی یا سونے کو کٹھالی میں ڈال کر پگھلایا اور آگ میں گرم کیا.تاکہ کھوٹے کو کھرے سے جدا کرے اور معلوم ہوجائے کہ وہ خالص ہے یا آمیزش والا ہے.اور یہی اصل معنی فتنہ کے ہیں.(اقرب) عَلَا عَالٍ عَلَا کا اسم فاعل ہے.عَلَا کے معنی ہیں.اِرْتَفَعَ اونچا ہوا.فِی الْاَرْضِ تَکَبَّرَ وَ تَجَبَّرَ.ملک میں ظالمانہ طریق پر حکومت کی.فُلَانًا غَلَبَہٗ وَقَھَرَہٗ دبا کر زیر کرلیا (اقرب) أَسْرَفَ.مُسْرِفٌ اَسْرَفَ کا اسم فاعل ہے.جس کے معنی ہیں جَاوَزَ الْحَدَّوَ اَفْرَطَ حد سے بڑھا.اَخْطَأَ غلطی کی جَھِلَ جہالت سے کام لیا.غَفَلَ غفلت دکھائی.(اقرب) تفسیر.جبر کا لازمی نتیجہ بغاوت ہے فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ الخ کے یہ معنی ہوئے کہ حضرت موسیٰ ؑ کی ان کی قوم کے ہی کچھ آدمیوں نے اطاعت کی اور دوسرے لوگوں نے اس ڈر کے مارے ان کی بات نہ مانی کہ فرعون انہیں تکلیف نہ پہنچائے یا عذاب میں نہ ڈالے یا ان کو جلا نہ دے.اس سے یہ بھی معلوم ہوتا
Page 174
ہے کہ انبیاء کے زمانہ میں لوگوں کے دل تو انہیں مان جاتے ہیں مگر ڈر کے مارے ظاہر میں انہیں نہیں مانتے.اور کھلے کھلے طور پر ان پر ایمان نہیں لاتے.کئی جابر بادشاہ ہوتے ہیںمگر وہ عقلمند بھی ہوتے ہیں.وہ لوگوں کو ایسے طور پر تنگ نہیں کرتے کہ جس سے لوگ ان کی بغاوت پر مجبور ہوں مگر فرعون بیوقوف تھا کہ اس نے ایسا طریق اختیار کیا.جس نے لوگوں کو اس کی بغاوت پر مجبور کر دیا.حضرت نوح ؑ اور ان کے ساتھیوں پر بھی ظلم و جبر ہوا.لیکن حضرت نوح ؑ کا زمانہ حقیقتاًاستہزاء کا زمانہ تھا.کیونکہ ان کی قوم ان کے مخالف تھی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو حقیر سمجھ کر ان کے مٹانے کے لئے اس قدر جدوجہد نہ کرتی تھی لیکن فرعون کے زمانہ میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ تھی اس لئے اس کو ان کے بڑھ جانے کا اور اپنے کمزور ہو جانے کا خوف تھا.اور اس لئے وہ ان پر جبر کرتا تھا مگر یہ اس کی بہت بڑی نادانی تھی ایسے بے وجہ تشدد اور ظلم سے بغاوت کو تقویت پہنچتی ہے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا.اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ساری قوم ان پر ایمان نہیں لائی تھی.بلکہ اس کا ایک حصہ ایمان لایا تھا جیسا کہ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ کا لفظ ظاہر کررہا ہے.اور باقی حصہ صرف سیاسی رنگ میں ساتھ مل گیا تھا.بعض مفسرین نے مِّنْ قَوْمِهٖ کی ضمیر کو فرعون کی طرف پھیرا ہے اور یہ مراد لی ہے کہ فرعون کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے لیکن پہلے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں.مَلَاۡىِٕهِمْکی ضمیر کا مرجع اس آیت میں مَلَاۡىِٕهِمْ کی ضمیر کے متعلق سوال ہے کہ یہ ضمیر کس طرف جاتی ہے.بعض کے نزدیک بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف جاتی ہے کیونکہ انہی کا ذکر ہے.اور بعض کے نزدیک فرعون کی قوم کے سرداروں کی طرف ان کے نزدیک بنی اسرائیل کا سردار انہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل محکوم تھے.میرے نزدیک کسی خاص طرف ضمیر کے پھیرنے کی ضرورت نہیں.ملک کے بڑے لوگ صرف قوموں کے لحاظ سے بڑے نہیں ہوتے بلکہ حکومت کے لحاظ سے بھی.پس حکومت کے جو بڑے لوگ تھے خواہ اسرائیلی ہوں یا فرعونی سب بنی اسرائیل کے بڑے لوگ کہلا سکتے ہیں اور فرعون دونوں ہی کے ذریعہ سے ظلم کیا کرتا تھا.
Page 175
وَ قَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ اور موسیٰ نے (اپنی قوم سے )کہا (کہ) اے میری قوم اگر یہ بات (درست) ہے کہ تم اللہ( تعالیٰ) پر ایمان تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ۰۰۸۵ لائے ہو.تو اگر( اس کے ساتھ) تم (اس کے) سچے فرمانبردار (بھی) ہو تو اسی پر بھروسہ کرو.تفسیر.حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم کو خدا تعالیٰ پر پورا اعتماد رکھنا چاہیے.تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کام کے پیچھے تم لگے ہو وہ خدا تعالیٰ کا کام ہے.بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں کام قومی کام ہے اس اصطلاح کو اسلام نے تسلیم نہیں کیا.وہ اس کی بجائے دینی کام یا خدا تعالیٰ کے کام کی اصطلاح کو پسند کرتا ہے.اس طرح ایک تو خدا تعالیٰ مدنظر رہتا ہے.دوسرے قوم پرستی کے تنگ دائرہ سے انسان آزاد رہتا ہے.اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ.کا جملہ بظاہر زائد معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے فرما چکا ہےاِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ3 لیکن درحقیقت یہ زائد نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق اور نئے معنی پیدا کرنے کے لئے آیا ہے.اسلام جب ایمان کے مقابل آجائے تو اس وقت ایمان کے معنی یقین کامل کے ہوتے ہیں اور اسلام کے معنی ظاہری اطاعت کے ہوتے ہیں.گویا اس موقع پر ایمان سے مراد قلبی اطاعت اور اسلام سے مراد ظاہری اطاعت ہوا کرتی ہے.پس اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر تم کو خدا تعالیٰ پر کامل یقین ہوچکا ہے تو اگر تم عملی طور پر اس ایمان کے ثمرات کو پرکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو.اور اپنے سب کام اسی کے سپرد کردو.اس آیت میں بتایا ہے کہ قلبی ایمان کے بعد عملی تغیر ہونا چاہیے.کیونکہ مومن کے لئے ایمان کا درجہ پہلے اور اسلام کا درجہ بعد میں آتا ہے.لیکن کمزور ایمان والے کے لئے اسلام کا درجہ پہلے اور ایمان کا درجہ بعد میں آتا ہے.کیونکہ کمزور ایمان والا پہلے اعمال شروع کرتا ہے پھر اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کا دل قوی ہو جاتا ہے.اور ایمان بھی مضبوط ہوجاتا ہے.لیکن جس شخص کو پختہ ایمان حاصل ہوتا ہے اس کے اعمال اس کے ایمان کے تابع ہوتے ہیں کیونکہ اس کی ترقی ذاتی ہوتی ہے.پس اصلاح کا کام بھی دل سے نکل کر ظاہر کی طرف آتا ہے.ادنیٰ درجہ کے آدمی کی اصلاح طفیلی ہوتی ہے.اور دوسرے کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے.اس وجہ سے باہر سے اندر کی طرف آتی ہے.اسی کی
Page 176
طرف اشارہ ہے اس آیت میں.کہ لَمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ (الحجرات :۱۵) یعنی تم لوگوں کو مسلمانوں کی صحبت سے ابھی ظاہری نقل کی توفیق ملی ہے.پس یہ تو کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی قلبی صفائی کا مقام تمہیں طے کرنا ہے.فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا١ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ اس پر انہوں نے کہا( کہ) ہم اللہ( تعالیٰ )پرہی بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں (ان) ظالم لوگوں کے الظّٰلِمِيْنَۙ۰۰۸۶ لئےفتنہ( کا موجب) نہ بنا.تفسیر.اس کے یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ ہم ایسے کام نہ کریں کہ ظالم لوگوں کو دین پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے اور یہ بھی کہ ہمیں ظالم قوم کے ظلموں کا تختہ مشق نہ بنا.وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۰۰۸۷وَ اَوْحَيْنَاۤ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں( کے ظلم) سے بچا لے.اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ مصرمیں چند مکانوں (کی جگہ) کو اپنی قوم کے( رہنے کے) لئے اختیار کرو اور تم (سب لوگ) اپنے( اپنے) گھر اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ١ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۰۰۸۸ آمنے سامنے بناؤاور( ان میں) عمدگی سے نماز ادا( کیا) کرو اور( یہ وحی بھی کی کہ اے موسیٰ ) تو مومنوں کو ( کامیابی کی) بشارت دے.حلّ لُغَات.تَبَوَّأَ تَبَوَّأَالْمَکَانَ وَبِہٖ اِتَّخَذَہٗ مَحَلَّۃُ وَاَقَامَ بِہٖ.یعنی تَبَوَّأَ الْمَکَانَ یا تَبَوَّأَ بِالْمَکَانِ کے معنی ہوتے ہیں اسے اپنی جائے رہائش بنا لیا.اور اس میں ٹھہرا.
Page 177
اَلْقِبْلَۃُ اَلْقِبْلَۃُ النَّوْعُ.قسم اَلْجِھَۃُ طرف.کہتےہیں مَالِھٰذَا الْاَمْرِ قِبْلَۃٌ.اَیْ جِھَۃُ صِحَّۃٍ اس بات کی درستی کی اور ٹھیک ہونے کی کوئی راہ نہیں ہے.اَلْکَعْبَۃُ کعبہ کو بھی قبلہ کہتے ہیں.کُلُّ مَایُسْتَقْبَلُ مِنْ شَیْءٍ.جس چیز کی طرف منہ کیا جائے اور مَالَہٗ فِی ھٰذَا قِبْلَۃٌ وَلَادِبْرَۃٌ کے معنی ہیں اسے اس بات کی کوئی راہ نظر نہیں آتی.اِجْعَلُوْا بُیُوْتِکُمْ قِبْلَۃً.اَیْ مُتَقَابَلَۃً اور اِجْعَلُوْا بُیُوْتَکُمْ قِبْلَۃً کے معنی ہیں متقابل یعنی آمنے سامنے.(اقرب) تفسیر.مصر میں گھر بنا کر رہو کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے جنگل میں رہتے تھے.بلکہ مراد یہ ہے کہ اکٹھے ہوکر رہو.تاکہ ایک دوسرے سے تعاون کرسکو.یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہوتی ہے.یہ ایک طبعی جذبہ ہے کہ کمزور جماعتیں شہروں میں اکٹھی ہوجاتی ہیں.پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے.یہاں ہندو لوگ شہروں میں اپنی نسبت آبادی سے زیادہ آباد ہیں.یوپی میں مسلمانوں کی آبادی کم ہے.وہاں مسلمان اپنی تعداد کی نسبت سے شہروں میں زیادہ آباد ہیں.اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً کے معنی وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً کے معنی قبلہ کے مختلف معنوں کی وجہ سے کئی ہوں گے.اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ ایک لفظ ہی کئی معانی پر دلالت کردے.پس جس قدر معنی سیاق و سباق کے رو سے لگ سکیں سب ہی مراد ہوسکتے ہیں.پس قبلہ کے متفرق معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ (۱) اکٹھے ہوکر رہنا چاہیے.کیونکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے گھر تب ہی ہوسکتے ہیں جب سب لوگ اکٹھے ہوکر رہیں.(۲) ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے.کیونکہ آمنے سامنے مکان بنانے کی غرض یہی ہوا کرتی ہے کہ وقت پر آسانی سے مدد کرسکیں.(۳) چونکہ قبلہ کے معنی جہت کے بھی ہیں.پس یہ بھی مراد ہے کہ ایک ہی طرف سب مکان ہوں یعنی سب جماعت ایک نظام کے ماتحت ہو اور متحدہ مقاصد کی پیروی کی جائے.(۴) قبلہ کے معنی نوع کے بھی ہوتے ہیں.پس یہ معنی بھی ہوں گے کہ ایک قسم کے مکان ہوں اور ان معنوں سے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قومی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ غریب و امیر میں مضبوط رابطہ ہو.اور ساری قوم ایک ہی رنگ میں رنگین نظر آئے تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل ہو.اگر ایک شخص محلات میں رہے گا اور دوسرا جھونپڑے میں تو ارتباط پیدا ہونا مشکل ہوگا.اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ میں دعاؤں کی طرف اور استقلال کے ساتھ کام کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے.کیونکہ اِقَامۃ استقلال پر دلالت کرتی ہے.
Page 178
ترقی کے سات گُر خلاصہ یہ کہ اس آیت میں سات گر ترقی کے بتائے ہیں.جن پر عمل کرکے دنیا کی ہر قوم ترقی کرسکتی ہے.یعنی (۱) اجتماع (۲) اتحاد (۳) تعاون (۴) نظام (۵) بڑے چھوٹوں میں ارتباط (۶) دعا (۷) استقلال.اور آخری گر نگراں کے لئے بتایا کہ وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِیْنَ کہ جو لوگ اطاعت کے حلقہ میں آجائیں ان کو کامیابی کی خوشخبری دے دے کر ان کا حوصلہ بڑھاتے رہنا چاہیے.کیونکہ مایوسی اور ناامیدی سب آفتوں سے بڑی آفت ہے.وَ قَالَ مُوْسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّ اور موسیٰ نے کہا( کہ) اے ہمارے رب تو نے( تو) فرعون (کو) اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کو (اس) ورلی اَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا١ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ١ۚ زندگی میں زینت (کے سامان) اور اموال دے رکھے ہیں.اے ہمارے رب( لیکن) اس کے نتیجہ میں وہ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا ( اوروں کو بھی) تیری راہ سےبرگشتہ کر رہے ہیں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ۰۰۸۹ (کی زمین) پر حملہ آور ہو (اور) پھر اس کے نتیجہ میں وہ جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں( آئندہ بھی) ایمان نہ لائیں گے.حلّ لُغَات.طَمَسَ طَمَسَ عَلَیْہِ اَھْلَکَہٗ اسے ہلاک کر دیا.طَمَسَہٗ.اِسْتَأْصَلَ اَثَرَہٗ اس کا نشان مٹا ڈالا.(اقرب) شَدَّ عَلَیْہِ شَدَّ عَلَیْہِ حَمَلَ عَلَیْہِ.اس پر حملہ کیا (اقرب) اس کے معنی دل کو سخت کرنے کے جو مفسرین نے لکھے ہیں یعنی ان کے دلوں کو سخت کر دے.وہ کسی لغت کی کتاب میں نہیں ملتے.لغت کی کتب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب حَمَلَ کے بعد علیٰ آئے تو اس کے معنی صرف حملہ کرنے کے ہوتے ہیں.زِیْنَۃٌکے معنی اَلزِّیْنَۃُ مَایُتَزَیَّنُ بِہٖ.حسن کے حصول اور عیوب کے زوال اور خفاء کا سامان اور ذریعہ (اقرب) یوں تو قرآن مجید نے ان سب چیزوں کو زینت فرمایا ہے جو زمین پر ہیں جیسا کہ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً
Page 179
لَّهَا (الکہف :۸) بلکہ حیات دنیا کو بھی زینت فرمایا ہےچنانچہ فرماتا ہے.اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ (الحدید:۲۱) مگر جہاں زِیْنَۃُ الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا کا ذکر فرماتا ہے وہاں پر لفظ زینت کا اطلاق دو ہی چیزوں یعنی مال و اولاد پر ہوتا ہے.جیسے کہ سورۂ کہف میں آتا ہے.اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (الکہف:۴۷) یعنی مال اور بیٹے دونوں ورلی زندگی کی زینت ہیں اور جہاں اقوام کی گمراہی کے ذکر میں زینت کا ذکر آتا ہے اس سے بھی حیٰوۃ دنیا کی زینت ہی مراد ہوتی ہے.جو اموال و اولاد پر مشتمل ہوتی ہے.لیکن یہاں پر زینت کا اطلاق مجرد اولاد پر ہوا ہے.کیونکہ یہاں زینت کے ساتھ اموال کا لفظ بڑھا دیا ہے.جو کہ حقیقت میں اس کے معنوں کا ایک حصہ تھا اور جب کسی حصہ کو الگ بیان کر دیا جائے تو لفظ صرف بقیہ معنوں پر دلالت کرتا ہے.جیسے اَسْرٰی رات کے سفر کو کہتے ہیں مگر اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا (بنی اسرائیل:۲) میں رات کا ذکر علیحدہ ہو جانے کی وجہ سے اسریٰ کے معنے مجرد سفر کرنے کے رہ گئے ہیں.تفسیر.لِیُضِلُّوْا کے لام کے معنی آیۃ کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اموال اور اولاد.آل فرعون کو اس لئے دیا تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بلکہ لِیُضِلُّوْا کا لام صیرورۃ اور عاقبۃ کا لام ہے.اور اس کے یہ معنی ہیں کہ تو نے تو ان کو مال و اولاد دیئے تھے لیکن بجائے شکر گذار بننے کے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ گمراہ کرنے لگ گئے ہیں.غرض لام اس جگہ علت پر دلالت نہیں کرتا.بلکہ نتیجہ پر دلالت کرتا ہے.اور یہ ایک طریق اظہار افسوس کا ہے کہ کیسی بدنصیب قوم ہے کہ اس قدر احسانات کے بعد بھی ناشکری کرتی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہے.فَلَا یُؤْمِنُوْاکے معنی فَلَا یُؤْمِنُوْا کا عطف لِیُضِلُّوْا پر ہے.یعنی گمراہ کریں گے اور ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں.رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰۤى اَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ کا جملہ معترضہ ہے.اور اس میں بددعا نہیں بلکہ حقیقت میں دعا کی گئی ہے.اس دعا کے معنی حضرت موسیٰ بیان فرماتے ہیں کہ خدایا تو نے تو ان کو مال و اولاد دیئے تھے چاہیے تھا کہ یہ شکر گذار بنتے لیکن یہ الٹے ناشکرے ہو گئے ہیں.اور اس قدر ترقی کی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گئے.اور اس حالت کو پہنچ گئے کہ عذاب الیم کے سوا ان کے دلوں کو تیری طرف کوئی چیز مائل ہی نہیں کرتی.پس میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے مالوں کو تباہ کر اور ان کے دلوں کو صدمہ پہنچا.یعنی اولاد کی طرف سے تکالیف پہنچا تاکہ انہیں ہدایت حاصل ہو کیونکہ یہ اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ سوائے عذاب کے ایمان کی طرف مائل نہیں ہوسکتے.پس ان کی
Page 180
ہدایت کی خاطر عذاب ہی لا کہ یہ ہدایت تو پائیں.غرض یہ گمراہی کی بددعا نہیں بلکہ ہدایت کی دعا ہے.آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی حالت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بغیر عذاب کے وہ ہدایت نہیں پاسکتے تھے.جس کی بناء پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ مال اور اولاد کا عذاب ان پر آئے تاکہ جو چیزیں ان کی گمراہی کا موجب ہوئی ہیں ان کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر یہ لوگ ہدایت کی طرف مائل ہوں.اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ ؑ نے عذاب کی دعا کی ہے لیکن جو لوگ بغیر سزا کے ہدایت نہ پاسکتے ہوں ان کے لئے عذاب کی دعا تو رحمت کی دعا ہے.جس طرح ایک خراب شدہ عضو کے کاٹنے کی استدعا ایک رحمت کا مطالبہ ہوتا ہے.غضب کی دعا تبھی بن سکتی تھی اگر ہدایت سے محروم رکھنے کی دعا ہوتی اور یہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے.اُشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ کے معنی دل پر حملہ کرنے کے معنی اولاد کی طرف سے تکلیف ہے.کیونکہ حملہ کا لفظ اولاد کے مقابلہ پر استعمال ہوا ہے اور یہ حملہ دو طرح ہوسکتا تھا.ایک اس طرح کہ اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے.اور ایک اس طرح کہ اولاد کو خدا تعالیٰ ہدایت دے دے.کیونکہ اولاد کا ساتھ چھوڑ کر دشمن سے مل جانا بھی ایک سخت صدمہ کا موجب ہوتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دشمنوں پر بھی یہی حملہ ہوا اور یہ حملہ سزا نہیں کہلا سکتا.حضرت موسیٰ کے زمانہ میں اس طرح یہ سزا ملی کہ فرعون کے ساتھیوں کے بڑے بیٹے مر گئے.ترتیب الفاظِ دعا یہ لطیفہ قرآنی ترتیب پر لطیف روشنی ڈالتا ہے کہ پہلے حصہ آیت میں لفظ زِیْنَۃٌ جو اولاد کا قائم مقام ہے اسے پہلے رکھا ہے اور اموال کو بعد میں.لیکن سزا کے ذکر میں اموال کے تباہ کر دینے کا پہلے ذکر ہے اور قلوب پر حملہ کرنے کا ذکر بعد میں آیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انعام کے وقت تو اولاد کا ذکر اس کے درجہ کے لحاظ سے مقدم کیا کیونکہ وہ بڑا انعام تھا لیکن جس جگہ سزا کی دعا تھی گو وہ ہدایت کے لئے ہی تھی وہاں چھوٹی سزا کا مطالبہ پہلے کیا اور بڑی سزا کا بعد میں.اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کہ اگر یہ لوگ صرف مالی ابتلاؤں سے ہدایت پا جائیں تو اولاد کی سزا سے ان کو بچا لیا جائے اولاد کی طرف سے تبھی دکھ دیا جائے جب پہلی قسم کا عذاب بے فائدہ ثابت ہو.اس ترتیب کے فرق میں جہاں قرآن کریم کی ترتیب کی خوبی ظاہر ہوتی ہے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کی رأفت پر بھی روشنی پڑتی ہے.ریورنڈ ویری اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دعا بائبل کے مخالف ہے.لیکن اول تو بائبل کی مخالفت کے معنی سچائی کی مخالفت کے نہیں ہوتے.دوسرے پادری صاحب نے چونکہ آیت کے غلط معنی کئے ہیں اس لئے اختلاف نظر آیا ہے ورنہ اصل میں کوئی اختلاف نہیں.
Page 181
قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ (اس پر اللہ تعالیٰ نے )فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے.پس تم( دونوں) ثابت قدمی دکھاؤ اور جو لوگ علم سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ۰۰۹۰ نہیں رکھتے ان کی راہ کی پیروی ہرگز نہ کرو.تفسیر.جواب دعا میں موسیٰ اور ہارون ہر دو کو مخاطب کرنے کی وجہ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعا تو حضرت موسیٰ ؑنے کی اور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا میں ربنا کا لفظ استعمال کیا گیا تھا جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے.پس دعا میں موسیٰ اور ہارون دونو شامل تھے.وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ میں مخالفین کی کوششوں کا اظہار کیا گیا ہے وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ فَاسْتَقِيْمَا کی تشریح ہے اور اس کے یہ معنی نہیں کہ نبی لوگوں کی باتوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ دشمن ہمیشہ اصل مقصد سے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کیا کرتے ہیں.تم ان سے ہوشیار رہنا اور ان کی ایسی بحثوں کی طرف توجہ نہ کرنا جو تم کو تمہارے اصل مقصد سے دور لے جائیں.وَ جٰوَزْنَا بِبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے (پار) گذارا تو فرعون اور جُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّ عَدْوًا١ؕحَتّٰۤى اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ١ۙ قَالَ اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم (کی راہ) سے ان کا پیچھا کیا.حتی کہ جب غرق ہونے (کی آفت) نے اسے آپکڑا اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ جس( مقتدر ہستی) پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی بھی معبود
Page 182
اِسْرَآءِيْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۰۰۹۱ نہیں ہے اور میں (سچی) فرمانبرداری اختیار کرنے والوں میں سے (ہوتا) ہوں.حل لغات.جَاوَزَ جَاوَزَ الْمَوْضِعَ تَعَدَّاہُ اس مقام سے گذر کر آگے نکل گیا.(اقرب) اِتَّبَعَ اِتَّبَعَ اور تَبِعَ میں تفریق کے متعلق اصمعی مشہور ادیب کا قول ہے کہ تَبَعَہُ لَحِقَہُ وَاَدْرَکَہٗ جب تَبِعَ کا لفظ استعمال کریں تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے گیا.اور اس کو پالیا.وَاتَّبَعَہٗ اِذَا تَبِعَ اَثَرَہٗ.اَدْرَکَہٗ اَوْلَمْ یُدْرِکْہُ اور اَ تَّبَعَ کا لفظ تب استعمال کرتے ہیں جب یہ مقصود ہو کہ وہ اس کے پیچھے گیا.خواہ اسے ملا ہو یا نہ مل سکا ہو.اَتْبَعَہٗ تَبِعَہٗ وَذٰلِکَ اِذَا کَانَ سَبَقہٗ فَلَحِقَہٗ.(قرطبی) اور اقرب الموارد میں ہے کہ اتبع کے معنی پیچھے جانے کے ہوتے ہیں بشرطیکہ جس کا پیچھا کیا جائے وہ آگے نکل چکا ہو.اور پیچھا کرنے والا پیچھے سے جاکر اس سے مل جائے.یہ معنی پہلے معنوں کے خلاف ہیں.اَدْرَکَ الشَّیْءَ.بَلَغَ وَقْتُہٗ اس کا وقت پہنچ گیا.(اقرب) تفسیر.اگر بادشاہ مذہبی امور میں جبر سے کام لے تو اس کے ملک کو چھوڑ دینا چاہیے یہاں ایک عظیم الشان سیاسی بات بیان کی ہے.اور وہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم بادشاہ کی فرمانبرداری کریں.لیکن اگر وہ ہمارے مذہبی امور میں دخل دے اور جبر سے کام لے تو ہم اس کے ملک سے ہجرت کرجائیں اور اگر وہ ہجرت کرنے سے بھی روکے تو اس وقت وہ بادشاہ باغی سمجھا جائے گا.اور اس کے ساتھ مقابلہ شرعاً جائز ہوگا.کیونکہ اس صورت میں ہم حق پر ہوں گے اب اس کی قانون شکنی قانون شکنی نہ رہے گی کیونکہ جس طرح کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کے ملک میں رہ کر پھر اس کے قانون کی خلاف ورزی اور قانون شکنی کرے اسی طرح کسی کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ باوجود مذہبی اختلاف کے کسی کو اپنے ملک میں رہنے پر مجبور کرے.بَغْيًا وَّ عَدْوًاکے معنی اس آیت میں بَغْیًا کہہ کر بتایا ہے کہ اس کو قانونی حق بھی باقی نہیں رہا تھا.اورعَدْوًا کہہ کر ظاہر کیا کہ اس کا اخلاقی حق بھی باقی نہیں رہا تھا.فرعون کا آخری وقت میں کمال تذلل فرعون کے ڈوبتے وقت کے کلمات میں کمال تذلل پایا جاتا ہے.اگر صرف موسیٰ کا رب کہتا تو پھر بھی کوئی بات نہ تھی.کیونکہ حضرت موسیٰ اس کے گھر میں پلے تھے.اور ان میں معزز سمجھے جاتے تھے.مگر فرعون کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں.گویا اس خدا پر جو اس کے پتھیروں کا خدا تھا.کیونکہ بنی اسرائیل کو وہ نہایت ذلیل سمجھتا تھا اور ان سے پتھیروں کا کام لیتا تھا.
Page 183
آٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ۰۰۹۲ کیا اب( تو ایمان لاتا ہے )حالانکہ پہلے تو نے نافرمانی کی.اور تو مفسدوں میں سے تھا.تفسیر.بعد از وقت ایمان سود مند نہیں ہوتا ایمان بھی خاص حالات میں ہی فائدہ دیتا ہے.جب حق بالکل کھل جائے تب ایمان کا نفع باقی نہیں رہ جاتا.کیونکہ ثواب محنت اور قربانی کے بدلہ میں ملتا ہے.اور جس بات کے سمجھنے کے لئے کوئی محنت نہ کرنی پڑے اس کا ثواب بھی کوئی حاصل نہیں ہوتا.فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً١ؕ پس اب ہم تیرے بدن (کے بقا) کے ذریعہ سے تجھے (ایک جزوی) نجات دیتے ہیں.تاکہ جو لوگ تیرے پیچھے (آنے وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَؒ۰۰۹۳ والے) ہیں.ان کے لئے تو ایک نشان ہو.اور لوگوں میں سے بہت سے (افراد) ہمارے نشانو ں سے یقیناً یقیناً بے خبر ہیں.تفسیر.خدا تعالیٰ کی جزائیں بھی عجیب پرحکمت ہوتی ہیں.فرعون ایسے وقت میں ایمان لایا کہ اس کا ایمان صرف ایک بے جان ڈھانچہ تھا.اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بدن کو بچا لیا.اور اس کے ایمان جیسی ہی اسے نجات دے دی.یعنی روح کو تو فائدہ نہ پہنچا جسم کو بچا دیا کہ دوسروں کے لئے عبرت ہو.فرعون کے جسم کا بچایا جانا نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ فرعون کے جسم کے بچائے جانے کا ذکر قرآن کریم کے سوا دوسری کتب میں نہیں ہے.بائیبل اس امر میں خاموش ہے.اور تاریخیں ساکت ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی باتیں کیسی سچی ہوتی ہیں آج تین ہزار سے زائد سالوں کے بعد فرعون موسیٰ یعنی منفتاح کی لاش مل گئی ہے.اور قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے.اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے.چھوٹے قد کا دبلا سا ایک شخص ہے جس کے چہر ہ سے حماقت اور غضب دونوں قسم کی صفات ظاہر ہوتی ہیں.کجا وہ زمانہ اور کجا یہ زمانہ.خدا تعالیٰ نے اس کے جسم کو نہ صرف بچایا بلکہ پچھلوں کے لئے اسے عبرت کا موجب بنانے کے لئے اس کی لاش کو اس وقت تک محفوظ رکھا ہے.صداقتِ قرآن پر زبردست نشان یہ آیت قرآن کریم کی سچائی پر کیسا زبردست شاہد ہے.اور بائیبل پر اس کی کس قدر فضیلت ثابت کرتی ہے.بائیبل کا دعویٰ ہے کہ وہ موسیٰ کے وقت کی تاریخ بیان کرتی ہے اور اسی وقت لکھی گئی تھی.قرآن کریم اس کے قریباً دو ہزار سال بعد آتا ہے اور وہ واقعات بیان کرتا ہے جو بائیبل میں بیان نہیں
Page 184
ہیں.اور پھر واقعات اسی کی صداقت ثابت کرتے ہیں.اور بائیبل ناقص ثابت ہوتی ہے.یہ کون سا فرعون تھا بعض مفسروں نے اس فرعون کا نام رعمسیس لکھا ہے لیکن یہ درست نہیں.رعمسیس وہ فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ کو پالا تھا.لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت کا زمانہ وہ ہے جبکہ اس کا دوسرا بیٹا منفتاح تختِ حکومت پر بیٹھا.بائیبل سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے.کیونکہ لکھا ہے کہ موسیٰ کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل رعمسیس نامی شہر بناتے تھے.(خروج باب ۱ آیت ۱۱) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کا نام رعمسیس تھا.پھر خروج ب۲ آیت ۲۳ میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ مر گیا.اور دوسرے کے پاس موسیٰ آئے.پس رعمسیس کا بیٹا منفتاح تھا جس کے پاس موسیٰ آئے تھے اور وہی غرق ہوا.(نیز دیکھو جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Merneptah) ایمان لانے میں توقف نہ کرنا چاہیے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان میں جلدی کرنی چاہیے.جب بھی نیک تحریک ہو اسے جلدی پورا کرنا چاہیے.اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا.اب دیکھو فرعون موت کے وقت ایمان لاتا ہے تو اس کی لاش کو امن دیا جاتا ہے.جب وہ لوگوں کی ہدایت کا موجب ہوگا تو کچھ نہ کچھ تو اسے اس کے ایمان کا فائدہ پہنچے گا.حضرت محی الدین ابن عربی کا اسی وجہ سے یہ مذہب ہے کہ فرعون جہنم میں نہیں جائے گا.(شرح القاشانی علی فصوص الحکم زیر عنوان فص موسوی) وَ لَقَدْ بَوَّاْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مُبَوَّاَ صِدْقٍ وَّ رَزَقْنٰهُمْ اور ہم نے یقیناً یقیناً بنی اسرائیل کو ظاہری اور باطنی (ہر قسم کی) خوبی والی جگہ دی تھی.اور( ہر قسم کی) پسندیدہ چیزیں مِّنَ الطَّيِّبٰتِ١ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ١ؕ اِنَّ (بھی)انہیں دی تھیں.پھر اس وقت تک کہ ان کے پاس( صحیح) علم آگیا.انہوں نے (کسی امر میں) اختلاف نہ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۰۰۹۴ کیا.تیرا رب ان کے درمیان اس (امر کے) بارہ میں جس میں وہ (اب) اختلاف کر رہے ہیں یقیناً قیامت کے دن فیصلہ کرے گا.حلّ لُغَات.بَوَّأَ مُبَوَّءٌ بَوَّءَمیں سے اسم ظرف یا مصدر میمی ہے.بَوَّأَہٗ وَبَوَّأَ لَہٗ مَنْزِلًا ھَیَّأَہٗ وَمَکَّنَ
Page 185
لَہٗ فِیْہِ (اقرب) جگہ دی.ٹھہرایا.پس مُبَوَّأٌ کے معنی ہیں ٹھہرانے کی جگہ یا ٹھہرانا.جگہ دینا.صِدْقٍ صدق ہر وہ چیز جو ظاہر و باطن طور پر اچھی ہو.(دیکھو سورۂ یونس زیر آیت نمبر۳) تفسیر.اَلطَّیِّبَاتُ.یعنی پاک چیزیں.پاک چیزوں میں سے سب سے مقدم الہام الٰہی ہے.کیونکہ وہ تازہ بتازہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے.اور دوسری چیزیں بھی مراد ہوسکتی ہیں.کیونکہ بنی اسرائیل فرعون کی اینٹیں مفت بنایا کرتے تھے.وہاں ان کو پاکیزہ رزق کہاں میسر آسکتا تھا.اس وقت تو وہ چوریاں وغیرہ ہی کرتے ہوں گے.مگر وہاں سے نکل کر ان کو رزق حلال مل گیا.علم سے مراد اور اَلْعِلْمُ سے مراد قرآن کریم ہے.نہ کہ تورات.کیونکہ تورات کے نزول اور بنی اسرائیل کی قوم کے قیام کے درمیان تو وقفہ ہی نہ تھا کہ جس میں وہ اختلاف کرسکتے.اختلاف سے مراد اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ کلام الٰہی کے ایک سے زیادہ معنی کرنے منع ہیں.کیونکہ یہ تو خود قرآن کریم کی دوسری آیات کے خلاف ہے.بلکہ اس جگہ اختلاف سے مراد ایک نبی کے متعلق اختلاف ہے.بنی اسرائیل سب کے سب متفق تھے کہ ایک نبی آئے گا لیکن جب وہ آ گیا تو اختلاف کر دیا.جس طرح آج مسلمانوں نے کیا.کہ مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کو سب مانتے تھے اور آمد کی پیشگوئیاں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کو بھی مانتے تھے.لیکن جب موعود آ گیا تو انہوں نے قبول نہ کیا.اور یہاں تک کہہ دیا کہ مسیح کی آمد کے متعلق پیشگوئیاں ہی وضعی ہیں.پس اختلاف سے مراد پیشینگوئیوں کے متعلق اختلاف ہے کہ پہلے تو ان کو مانتے رہے لیکن مصداق کے ظہور کے وقت بعض نے اس کا انکار کر دیا.اور بعض نے پیشینگوئیوں تک کا انکار کر دیا.مَا اخْتَلَفُوْا سے مراد توراۃ نہیں اس امر کا ثبوت اس جگہ مَا اخْتَلَفُوْا سے مراد توراۃ نہیں ہے.یہ ہے کہ آگے چل کر فرمایا ہے فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الخ (یونس:۹۵) کہ اے مخاطب اگر تجھے اس کلام الٰہی میں کوئی شک ہے جو ہم نے تجھ پر اتارا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں بھی نزول قرآن ہی کا ذکر ہے.یہود موسیٰ ؑ کی مانند ایک نبی کی آمد کا جو عرب میں پیدا ہونے والا تھا اس قدرا نتظار کررہے تھے کہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ بعض یہود نے مدینہ میں آکر پہلے ہی سے بودوباش اختیار کرلی تھی.تاکہ اس نبی کو سب سے پہلے ماننے والوں میں سے وہ ہوں.لیکن جب وہ نبی آ گیا.تو اس کے سب سے بڑے دشمن وہی ثابت ہوئے.
Page 186
فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ پھر اگر تو اس( کلام) کی وجہ سے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہےکسی شک (و شبہ) میں (مبتلا )ہے تو تو ان لوگوں يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ١ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ سےجو تجھ سےپہلے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں دریافت کریقیناً یقیناً (ایک) کامل صداقت تیرے رب کی طرف رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَۙ۰۰۹۵ سے تیری طرف آئی ہے پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن.تفسیر.شک کرنے والے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے فَاِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوسکتے کیونکہ جس پر کلام نازل ہوتا ہے اس کو شک نہیں ہوسکتا.پس اس سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں.قرآن کریم شک پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا نیز اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم سے شک پیدا ہوتا ہے بلکہ اس جگہ کفار کے اعتراض کے الفاظ دہرائے ہیں.وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن کریم کی عبارتوں سے شکوک پیدا ہوتے ہیں.اللہ تعالیٰ انہی کے الفاظ کو دہرا کر فرماتا ہے کہ اے معترض اگر تجھے بقول تیرے اس کلام سے شبہات پیدا ہوتے ہیں تو جو لوگ تجھ سے پہلے قرآن کریم کو پڑھ کر فائدہ اٹھا چکے ہیں ان سے پوچھ کہ ان کے دلوں کو اس کتاب نے کیسی جلا اور روشنی عطا کی ہے.ان سے سوال کرنے پر تجھے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام شک پیدا کرنے والا نہیں بلکہ یقین پیدا کرنے والا ہے.تعلیم کے لئے کتاب کے علاوہ معلم انسان کا ہونا بھی ضروری ہے اس آیت سے یہ بات بوضاحت ظاہر ہوجاتی ہے کہ خالی کتاب کافی نہیں ہوتی.انسان معلم کا بھی محتاج ہوتا ہے کیونکہ روحانی علوم کے انکشاف کے لئے ایک حد تک روحانیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے.پس چاہیے کہ جب الہامی کتاب کا انسان مطالعہ کرے تو جن امور کے متعلق اسے شک ہو ان کے متعلق اس کتاب کے ماہرین سے دریافت کئے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے.کیونکہ اگر وہ کتاب الہامی ہے تو ضرور اس کا فہم روحانیت کے مطابق نازل ہوگا.
Page 187
بعض لوگ غلطی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ شک کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں.اور جن سے پوچھنے کا حکم ہے وہ یہود و نصاریٰ ہیں.مگر جیسا کہ پہلے ثابت کیا جاچکا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نہیں ہوسکتے.اور نہ آپ کے صحابہ.کیونکہ ان کی نسبت قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ١ؔ۫ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ( یوسف :۱۰۹) تو کہہ دے کہ میں اور میرے متبع صرف گمان سے اس مذہب کو نہیں مان رہے بلکہ ہم نے مشاہدہ سے قرآن کریم کی سچائی کو معلوم کرلیا ہے.اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ کسی امر کو مشاہدہ سے تسلیم کریں وہ اس کے متعلق شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوسکتے.اگلی آیت بھی بتاتی ہے کہ اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہوسکتے.وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ اور تو ان (لوگوں) میں سے ہرگز نہ بن جنہوں نے اللہ (تعالیٰ) کے نشانوں کو جھٹلا دیا ہے ورنہ تو نقصان اٹھانے الْخٰسِرِيْنَ۰۰۹۶اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ۰۰۹۷ والوں میں سے ہو جائے گا.جن لوگوں پر تیرے رب کی (طرف سے ہلاکت کی) بات واجب ہو چکی ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے.حلّ لُغَات.کَلِمَۃٌ.اَلْکَلِمَۃُ اللَّفْظَۃُ منہ سے بولا ہوا مفرد لفظ.ہر وہ بات جو انسان بولے.خواہ مفرد ہو.خواہ مرکب.وَالْعَشْرُ کَلِمَاتُ وَصَایَا اللہِ الْعَشْرُ.عشر کلمات اللہ تعالیٰ کے دس حکموں کو کہتے ہیں.الْخُطْبَۃُ وَالْقَصِیْدَۃُ.کبھی خطبہ اور قصیدہ کو بھی کلمہ کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.اس جگہ کلمہ سے مراد انذار کی بات کے ہیں.یعنی جو لوگ انذار کے مستحق ہوگئے ہیں اور اس سے بچنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی وہ ایمان نہیں لائیں گے.اس آیت سے ثابت ہے کہ صرف ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی پیشگوئی تھی جنہوں نے انذار سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا.نہ کہ سب کفار کے متعلق.
Page 188
وَ لَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ۰۰۹۸ جب تک کہ دردناک عذاب( نہ) دیکھ لیں.گو ان کے پاس تمام( قسم کے) نشان آچکے ہیں.تفسیر.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سچائی سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتے انہیں آیات نفع نہیں دیا کرتیں.اور بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کی نظروں میں دھوکا اور فریب ہوتا ہے.پس معاندین کا خواہ وہ کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہوں یہ کہنا کہ فلاں شخص نے معجزہ نہیں دکھایا.کوئی دلیل نہیں ہوتا.ہر شخص کو اپنے لئے خود غور کرکے فیصلہ کرنا چاہیے اور معجزات کو سنت انبیاء پر پرکھنا چاہیے.تاکہ حق سے محروم نہ رہ جائے.فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ اِيْمَانُهَاۤ اِلَّا قَوْمَ اور یونس کی قوم کے سوا کیوں کوئی (اور ایسی) بستی نہ ہوئی جو (سب کی سب) ایمان لاتی.تو اس کا ایمان لانا اسے نفع يُوْنُسَ١ؕ لَمَّاۤ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي دیتا جب وہ( یعنی یونس کی قوم کے لوگ) ایمان لائے تو ہم نے ا ن( پر) سے اس ورلی زندگی میں( بھی) رسوائی کا الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ۰۰۹۹ عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک (ہر طرح کا) سامان عطا کیا.حلّ لُغَات.قَرْیَۃٌ.اَلْقَرْیَۃُ اَلْمِصْرُ الْجَامِعُ بڑا شہر.کُلُّ مَکَانٍ اِتَّصَلَتْ بِہٖ الْاَبْنِیَۃُ وَاتُّخِذَ قَرَارًا ہر آبادی کی جگہ خواہ شہر ہو یا گاؤں.جَمْعُ النَّاسِ.لوگوں کی جماعت (اقرب) خِزْیٌ اَلْخِزْیُ اَلْھَوَانُ ذلت.ذلیل و حقیر ہونا.اَلْعِقَابُ.سزا.اَلْبُعْدُ دوری.اَلنَّدَامَۃُ شرمندگی پچتانا.وَاَصْلُ الْخِزْیِ ذُلّ یُسْتَحْیٰی مِنْہُ اس کے اصل معنی ایسی ذلت کے ہیں جو لوگوں کے سامنے شرمندگی کا موجب ہو.(اقرب) حِیْنَ الْحِیْنُ وَقْتٌ مُبْھِمٌ یَصْلُحُ لِجَمِیْعِ الْاَزْمَانِ طَالَ اَوْقَصُرَ.مطلق وقت خواہ بہت ہو خواہ تھوڑا.وَقِیْلَ الدَّھْرُ.بعض محققین لغت نے اس کے معنی زمانہ کے بتائے ہیں.اَلْمُدَّۃُ.مدت (اقرب) تفسیر.کاش ہر ایک نبی کی قوم یونس ؑ کی قوم کا نمونہ دکھاتی غور کرنے والے کے لئے اس
Page 189
آیت میں رحمتِ الٰہی کی عظمت معلوم کرنے کا بے انتہاء سامان موجود ہے.الفاظ سے کس قدر خواہش ٹپکتی ہے کہ سب کی سب دنیا ہدایت پا جائے کس قدر افسوس کا اظہار یہ الفاظ کررہے ہیں کہ کیوں یونس کی قوم کی طرح پوری کی پوری ایمان لانے والی اور اقوام نہ ہوئیں.اس پر جب عذاب آیا تو اس قدر اخلاص سے تائب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا.اور اسے عذاب سے نجات دی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا.فتح مکہ کے موقع پر سب قوم نے اطاعت قبول کرلی اور عذاب سے محفوظ ہوگئی.آخر ایمان بھی لے آئی.اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وارث بنی.اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثیل یونس بھی بن گئے.حضرت یونس کا ذکر قرآن اور حدیث میں حضرت یونس جن کا اس آیت میں ذکر ہے ایک نبی ہیں.جن کا ذکر قرآن شریف میں چھ جگہ آیا ہے.سورۂ صٰفّٰت ع۵ میں ان کے مرسل ہونے کا ذکر ہے.اور سورہ انعام (ع۱۰) اور سورۂ نساء (ع۲۳) میں انہیں نبیوں میں شمار کیا ہے.سورۂ انبیاء (ع۶) اور سورۂ ن (ع۲) میں بجائے نام کے ذاالنون اور صاحب الحوت کی صفت سے ان کا ذکر کیا ہے.کیونکہ ان کے ساتھ مچھلی کا واقعہ پیش آیا تھا.حدیث نہی تفضیل بر یونس اور اس کے معنی احادیث میں بھی ان کا ذکر آتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ مَایَنْبَغِیْ لِعَبْدٍ اَنْ یَقُوْلَ اَنَاخَیْرٌ مِنْ یُوْنُسُ ابْنِ مَتّٰی (مسلم کتاب الفضائل باب فی ذکر یونس و قول النبی ؐ ) کسی بندہ کو جائز نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ یونس بن متی سے افضل ہے اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے افضل نہیں تھے.بلکہ اس کی وجہ شارحین حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت یہ بات آپ نے فرمائی اس وقت تک آپ پر اپنی افضلیت واضح نہ ہوئی تھی.لیکن بعد میں آپ نے خود فرمایا کہ اَنَا سَیِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ.(صحیح مسلم کتاب الفضائل باب تفضیل نبینا علی جمیع الخلائق) میں بنی نوع انسان میں سے سب سے افضل اور سب کا سردار ہوں.آنحضرت ؐ کی قوم کا فتح مکہ کے موقعہ پر بچایا جانا میرے نزدیک اس کی ایک اور بھی وجہ ہے جو اس آیت کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے.اور وہ یہ کہ اس جگہ کلی فضیلت کا ذکر نہیں بلکہ جزوی فضیلت کا ذکر ہے.اور وہ وہی فضیلت ہے جو اس آیت میں مذکور ہے.یعنی ان کی قوم سب کی سب عذاب دیکھ کر ایمان لے آئی.حالانکہ کسی اور نبی کی قوم کو ایسا موقع نہیں ملا.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ جب تک اپنی قوم کا انجام نہ دیکھ لیں اس امر میں یونسؑ پر اپنے آپ کو فضیلت دیں.لیکن بعد کے واقعات نے یہ فضیلت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ کی قوم بھی غزوۂ فتح مکہ کے وقت تائب ہوئی.اور سب کی سب ایمان لاکر عذاب سے محفوظ ہو گئی.
Page 190
حضرت یونس کا ذکر بائیبل میں علماء بائیبل کے بیان کے مطابق حضرت یونس گاتھ ہیپر (GATH HAPPER) ضلع زیبون میں پیدا ہوئے.اس وقت یربعام (JOROBOAM) بادشاہ کا زمانہ تھا.جس کی حکومت ۷۸۱ قبل مسیح سے ۷۴۱ تک رہی ہے(انسائیکلو پیڈیا ببلیکا آف ویسٹ منسٹر ).اس بادشاہ کا ذکر ۲سلاطین باب ۱۴ میں آتا ہے.بائیبل میں ایک کتاب بھی یونہ نبی کی کتاب کے نام سے درج ہے.لیکن محققین میں اختلاف ہے کہ یونہ جس نے بنی اسرائیل کی ادو میوں سے آزادی کی خبر دی تھی وہی ہے جس کی وہ کتاب ہے یا اور کوئی شخص ہے.بائیبل کی کتاب یونہ میں یونس نبی کا حال یوں درج ہے کہ خدا کی طرف سے ان کو نینوا NENVAH کی طرف جو کہ ایک بڑا اور شرارتی شہر تھا جانے کا حکم ہوا تھا.اور انہیں حکم تھا کہ وہ اس کے خلاف پیشگوئی کریں.مگر حضرت یونسؑ ڈرے کہ نینوا والے توبہ کرلیں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے.پس وہ بجائے نینوا کے یافا چلے گئے اور ترشیش کی طرف جانے والے ایک جہاز میں سوار ہو گئے.لیکن دفعۃً جہاز کو طوفان نے آ گھیرا.ملاحوں نے دیوتاؤں سے بہت دعائیں کیں.مگر کچھ فائدہ نہ ہوا.آخر قرعہ ڈال کر انہوں نے دریافت کیا کہ یہ عذاب کس کے سبب سے ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرعہ میں نکلا.اور انہوں نے ان سے جاکر حال پوچھا انہوں نے اپنا سب حال بتایا اور کہا کہ میں خدا تعالیٰ کے حکم سے بھاگا ہوں.مجھے پانی میں پھینک دو.اس طرح عذاب سے محفوظ رہوگے.چنانچہ لوگوں نے انہیں پانی میں پھینک دیا.اور طوفان تھم گیا.خدا تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی.اس کے پیٹ میں حضرت یونس تین دن رات رہے.آخر ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں اگل دے.چنانچہ مچھلی نے ان کو اگل دیا.جب وہ اچھے ہوئے تو پھر خدا تعالیٰ کے حکم سے نینوا کو خبردار کرنے گئے.اور خبر دی کہ چالیس دن تک نینوا برباد کیا جائے گا.لیکن لوگوں نے توبہ کی اور گنہ سے باز آ گئے.تب اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹلا دیا.حضرت یونس کو یہ امر بہت شاق گزرا.اور وہ جنگل کی طرف چلے گئے.وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ارنڈ کا درخت ان کے سایہ کے لئے اگایا.جس کے نیچے وہ آرام کرنے لگے.مگر پھر ایک کیڑے کے ذریعہ سے اسے تبہ کرا دیا.سایہ کے نہ ہونے سے انہیں تکلیف ہوئی.تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے.اس پر خدا تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ تو ایک درخت کی ہلاکت پر جسے تو نے نہیں اگایا رنجیدہ ہوتا ہے.تو میں اپنے لاکھوں بندوں کو جنہیں خود میں نے پیدا کیا ہے کس طرح بلاوجہ تباہ کرسکتا ہوں.قرآن کریم کی رو سے بائیبل کے بیان پر نظر قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیبل میں حضرت یونس کے متعلق جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ غلط ہیں.کوئی نبی کسی حکم الٰہی کی خلاف ورزی نہیں کرتا اوّل قرآن کریم اس بات کا مخالف ہے کہ خدا کا کوئی نبی
Page 191
خدا تعالیٰ کا بالصراحت کوئی الہام سن کر اس کا انکار کر دے.اگر یہ بات ہو تو پھر امان ہی اٹھ جائے.فرماتا ہے وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ(النساء: ۶۵) اور پھر فرماتا ہےفَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ (الانعام:۹۱ ) انسان کو چاہیے کہ سب نبیوں کی پیروی کرے.اور اصلی مغز جو ان کے عمل کا ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرے.اگر انبیاء ایسے شدید امراض میں مبتلا ہوسکتے تو کبھی ان کی پیروی کا حکم نہ دیا جاتا.حضرت یونس یہود کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے دوم قرآن شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونسؑ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے.اور یہودی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی تھے لیکن نینوا والوں کی طرف بھیجے گئے تھے.جو کہ اشور کا دارالخلافہ تھا.اور وہاں کے لوگ اشور قوم کے تھے.اشور سے مراد سیریا یعنی شام کا علاقہ نہیں بلکہ یہ الگ علاقہ ہے.اور شہر بابل کے شمال سے شروع ہوکر ارمینیا کی سرحد سے جا ملتا ہے.اور مشرقی سمت اس کی کردستان سے ملتی ہے اور مغربی سمت دجلہ کے مغرب کے علاقہ کے ایک حصہ پر مشتمل ہے.گویا موجودہ عراق کا ایک حصہ اس میں شامل ہے ایک زمانہ میں اس علاقہ میں زبردست حکومت قائم تھی.اس کادارالخلافہ پہلے تو اسور تھا جو موصل سے ساٹھ میل جانب شمال واقع تھا اور اب اسے قلعات شرجت کہتے ہیں.لیکن قریباً تیرہ سو سال قبل مسیح اس شہر کو چھوڑ کر نینوہ کو دارالحکومت قرار دیا گیا.پس قرآن کریم کے بیان کے رو سے یا تو حضرت یونس بنی اسرائیل میں سے نہ تھے اور یا پھر وہ نینوہ کی طرف نہیں بھیجے گئے.بلکہ کسی اسرائیلی قبیلہ کی طرف بھیجے گئے تھے.محققین یورپ بھی اس بارہ میں مختلف الخیال ہیں کہ آیا یونس بنی اسرائیلی تھے یا نہیں.ہر عقلمند غور کرکے سمجھ سکتا ہے کہ قرآنی بیان دونوں اختلافات کے متعلق معقول ہے اور بائیبل کابیان خلاف عقل.وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا١ؕ اور اگر اللہ( ہدایت کے معاملہ میں) اپنی( ہی) مشیت کو نافذ کرتا تو جو (اور جس قدر) لوگ زمین پر (موجود) ہیں وہ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ۰۰۱۰۰ سب کے سب ایمان لے آتے (پس جب خدا تعالیٰ بھی مجبور نہیں کرتا )تو کیا تو لوگوں کو( اتنا) مجبور کرے گا کہ وہ مومن بن جائیں.تفسیر.خدا تعالیٰ لوگوں کے ایمان لانے کو پسند کرتا ہے مگر اس کے لئے مجبور نہیں کرتا پہلے فرمایا تھا کہ لَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَاۤ اِيْمَانُهَاۤ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ.جس میں ایک رنگ میں اس خواہش کا
Page 192
اظہار تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں.اس پر سوال ہوتا تھا کہ جب خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے تو کیوں اپنی خواہش کو پورا نہیں کرلیتا.اور سب کو مومن بنا دیتا؟ اس کا کیا لطیف جواب دیا ہے کہ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا.اگر خدا تعالیٰ اپنی خواہش کو جبریہ طور پر پورا کرنا چاہتا تو پھر کسی ایک قوم کی ہدایت تک کیوں جبر کو محدود رکھتا.کیوں نہ ساری دنیا ہی کو ہدایت دے دیتا.لیکن وہ ایسا نہیں کرتا.بلکہ ایمان کے معاملہ کو اس نے انسان کے اپنے دل پر چھوڑا ہوا ہے.ہاں وہ پسند یہی کرتا ہے کہ اس کے سب بندے ہدایت پاکر اعلیٰ درجات حاصل کریں.اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ کے معنی دوسرے حصہ آیت کے دو معنی ہیں.یہ حصہ پہلے حصہ کی دلیل بھی قرارد یا جاسکتا ہے.یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ جبر کرے کیونکہ جبر سے منوانا فائدہ بخش نہیں ہوتا.عقل مند انسان بھی جبر سے کسی کو نہیں منواتا.فرمایا اے ہمارے رسول کیا تو پسند کرے گا کہ لوگوں کو جبر سے منوائے نہیں تو ایسا پسند نہیں کرے گا.پس یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے جبر سے لوگوں کو منوائے؟ دوسرے معنی اس کے یہ ہوسکتے ہیں کہ اس میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ہر مسلمان سے ہے.اور یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر جوش میں آکر جبر سے کام نہ لینا اور یہ امر مدنظر رکھنا کہ جب خدا تعالیٰ جو مالک و آقا ہے جبر نہیں کرتا تو تم کون ہو جبر کرنے والے؟ اسلام کو جبراً پھیلانے کی سخت ممانعت بہرحال دونوں معنوں میں سے کوئی سے معنی بھی لئے جائیں یہ آیت جبر سے اسلام پھیلانے کی سخت مخالف ہے.اور ان لوگوں کے اعتراض کو پاش پاش کر دیتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جبر سے اشاعت دین کی تعلیم دی ہے.مسلمانوں نے نہ مکی زندگی میں ہی جبر سے کام لیا نہ مدنی زندگی میں اس آیت سے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے ممکن نہیں کہ مسلمانوں نے اشاعتِ اسلام میں جبر سے کام لیا ہو.کیونکہ ابتدائی زمانہ کے مسلمان نہایت سختی سے قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے تھے.اور یہ ممکن نہیں کہ جبکہ مسلمانوں کو حکومت کے ملنے سے پہلے بلکہ اس زمانہ میں جبکہ وہ مکہ مکرمہ میں کفار کے ظلموں کے شکار ہورہے تھے جبر سے روکا جارہا تھا.وہ حکومت ملنے پر جبر کرنے لگ جاتے.
Page 193
وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ١ؕ وَ يَجْعَلُ اوراللہ (تعالیٰ) کے( دئیے ہوئے) اذن کے سوا( کسی طور پر) ایمان لانا کسی شخص کے اختیا رمیں نہیں اور وہ( ایمان نہ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ۰۰۱۰۱ لانے کی وجہ سے )اپنا غضب ان (ہی) لوگوں پر (نازل) کرتا ہے جو عقل( رکھتے ہوئے اس) سے کام نہیں لیتے.حلّ لُغَات.اَذِنَ اَذِنَ بِالشَّیْءِ اِذْنًا عَلِمَ.جانا.معلوم کیا.لَہٗ فِی الشَّیْءِ اَبَاحَ اجازت دی.اَلْاِذْنُ اَلْاِجَازَۃُ جانے دینا.اجازت دینا.اَلْاِرَادَۃُ چاہنا.اَلْعِلْمُ جاننا (اقرب) رِجْسٌ اَلرِّجْسُ اَلْقَذِرُ.گند.اَلْمَأْثَمُ گناہ.گناہ کا کام.اَلْعَمَلُ الْمُؤَدِّیْ اِلَی الْعَذَابِ ایسا کام جس کا نتیجہ عذاب اور سزا ہو.اَلشَّکُّ شک.اَلْعِقَابُ سزا.اَلْغَضَبُ ناراضگی.(اقرب) تفسیر.ایمان خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قواعد پر چلنے کے سوا کسی طریق سے حاصل نہیں ہو سکتا اس آیت کے دو معنی ہیں.اوّل یہ کہ اس آیت میں جبر سے باز رہنے کے دلائل دیئے ہیں اور فرمایا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی جان سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن کے یقین لے آئے.یعنی یقین خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قواعد کے ماتحت پیدا ہوتا ہے.خالی منہ کے اقرار سے نہیں پیدا ہوتا.پس تم جبر کرکے یقین نہیں پیدا کرسکتے.اور جو لوگ عقل سے نہیں مانتے یونہی بے سوچے سمجھے مانتے ہیں ان کے ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے.بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر وبال ہی آتا ہے.پس اگر تم ظاہری طور پر لوگوں سے اقرار کرا بھی لو تو اس کا فائدہ کچھ نہ ہوگا.کیسے نادان لوگ ہیں جو باوجود ان تعلیمات کے قرآن کریم پر جبر کا الزام لگاتے ہیں.قرآن کریم تو بدلائل جبر کی تعلیم کے خلاف وعظ کرتا ہے.اس تعلیم کو منسوخ کرنے والے بھی ناواقف لوگ ہیں.کیونکہ حقیقی دلائل کبھی رد نہیں ہوا کرتے.جبر کے خلاف یہ دلائل تو ہر زمانہ میں درست ثابت ہوتے ہیں.پھر ان کی منسوخی کے کیا معنی.انبیاء اور نشانات کے ذریعہ سے منوانا جبر و اکراہ نہیں دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ پہلی آیۃ یعنی اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (یونس:۱۰۰) پر یہ اعتراض پڑ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا.تو پھر انبیاء کے ذریعہ سے شریعت کیوں بھیجتا ہے.اور انذار و تبشیر سے کیوں کام لیتا ہے.یہ بھی تو ایک قسم کا اکراہ ہی ہے.سو اس کا جواب اس آیت میں دے دیا ہے کہ انبیاء کے ذریعہ سے ہدایت کا اعلان کرنا اور اپنی قدرتوں کے
Page 194
ذریعہ سے ایمان کو مضبوط کرنا جبر نہیں ہے.بلکہ یہی واحد ذریعہ ایمان پیدا کرنے کا ہے.بغیر اس کے کہ خدا تعالیٰ اپنی مرضی کے حصول کا طریق بتائے لوگ اس تک پہنچ ہی کب سکتے ہیں.پس اگر اس طریق کو اختیار نہ کیا جاتا تو ہدایت پانا کسی کے لئے بھی ممکن نہ ہوتا.ان معنوں کے وقت اذن کے معنی ارادہ کے ہوں گے یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ سے ہدایت کا سامان مہیا نہ کرے.انسان ہدایت نہیں پاسکتا.وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور اذن کو نہیں مانتے ان پر ہم جبر نہیں کرتے.ہاں ان کے فعل کے مطابق ہم نتیجہ نکال دیتے ہیں.چونکہ وہ بدی کی طرف جاتے ہیں اس لئے ہم یہ نتیجہ نکال دیتے ہیں اور یا یہ کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے انہی کو ہم بدی میں مبتلا ہونے دیتے ہیں دوسروں کو نہیں.قُلِ انْظُرُوْا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ وَ مَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ تو (انہیں )کہہ (کہ) دیکھو (تو) آسمانوں اور زمین میں کیا( ہو رہا) ہے اور (نصرت الٰہی کے) نشانات اور( عذاب وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ۰۰۱۰۲ سے) متنبہ کرنے والے ان لوگوں کو جو( ضد سے) ایمان نہیں لاتے (کچھ بھی) فائدہ نہیں پہنچاتے.حلّ لُغَات.غِنَاءٌ.مَایُغْنِیْ عَنْکَ ھٰذَا اَیْ مَایُجْدِیْ عَنْکَ (اقرب) یعنی اَغْنٰی عَنْہُ کے معنی ہیں فائدہ پہنچانا.نُذُرٌ.اَلنُّذُرُ نَذِیْرٌ کی جمع ہے جس کے معنی متنبہ کرنے والے کے ہیں.(اقرب) تفسیر.آسمانی اور زمینی نشانات اور ترقی کے سامانوں کے ہوتے ہوئے جبر کی ضرورت ہی کیا ہو سکتی ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے سامان آسمان و زمین میں پیدا ہورہے ہیں.پس کسی جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے.آخری حصہ آیت نے صاف بتا دیا ہے کہ آسمان و زمین کی طرف توجہ دلانے سے مراد نشانات ارضی و سماوی ہیں.تبھی تو فرماتا ہے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا اور ضد سے کام لیتے ہیں اُن کو نشانات بھی فائدہ نہیں پہنچاتے.
Page 195
فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ پھر کیا جو لوگ ان سے پہلے گذر چکے ہیں ان کے ایام (کے نمونہ) کے سوا وہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں.تو قَبْلِهِمْ١ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ۰۰۱۰۳ ( ان سے)کہہ( کہ اچھا اگر وہی نمونہ دیکھنا ہے تو) پھر تم( لوگ کچھ) انتظار کرو.میں (بھی )یقیناً تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں.حلّ لُغَات.اَ یَّامُ اللہِ اَ یَّامُ اللہ نِعَمُہٗ وَنِقَمَہٗ.ایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے عذاب ہوتے ہیں.وَعَلَیْہِ فِی الْقُرْانِ وَذَکِّرْھُمْ بِاَیَّامِ اللہِ اَیْ ذَکِّرْھُمْ بِنِعَمِہٖ وَنِقَمِہٖ اور یہی معنی اس لفظ کے آیت فَذَکِّرْھُمْ بِاَیَّامِ اللہِ میں ہیں.(اقرب) اور زمخشری کی کتاب اساس میں ہے کہ ایام اللہ وہ ہلاکتیں اور تباہیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے منکرین پر آئیں.ھُوَ عَالِمٌ بِاَیَّامِ الْعَرَبِ اَیْ بِوَقَائِعِھَا.ایام العرب سے مراد عرب کی مشہور لڑائیاں اور معرکے ہیں.(اقرب) پس معنی اس آیت کے یہ ہوئے کہ وہ نہیں انتظار کرتے مگر ویسے ہی عذابوں کا جو ان قوموں پر آئے جو ان سے پہلے گذر چکی ہیں.یہاں چونکہ دشمن مخاطب ہیں اس لئے نقم ہی کے معنی کئے جائیں گے.تفسیر.ظالم کفار کا تاخیر عذاب پر گھبرانا اور مظلوم مومنوں کا مطمئن ہونا یعنی جو ضد کرتے ہیں آخر عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں.پس ان کو خود عذاب مانگنے کی ضرورت نہیں.وہ تو خود ہی اپنے وقت پر آکر رہے گا.یہ عجیب بات ہے کہ کفار جو اپنے وقت میں غالب ہوتے ہیں اور نبیوں اور ان کی جماعتوں کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں عذاب کے لئے گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہیں.لیکن نبی اور ان کی جماعتیں نہیں چاہتے کہ وہ جلد آئے.اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلواتا ہے کہ میں بھی تو عذاب کا انتظار کررہا ہوں.اور گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرتا.حالانکہ تمہارے ظلموں کا تختۂ مشق بن رہا ہوں پھر تم جو آرام میں ہو اور ظلم کے مرتکب ہورہے ہو کیوں اس قدر گھبرا رہے ہو.کوئی مانے یا نہ مانے تم تبلیغ کئے جاؤ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے.تبلیغ کس کو کریں.انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اعلان کا ارشاد ہوا تھا کہ اگر تم میری بات نہ
Page 196
بھی سنو گے تو بھی میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گا.اور کہتا چلا جاؤں گا.ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ١ۚ حَقًّا عَلَيْنَا پھر( جب وہ عذاب آجائےگا تو اس وقت) ہم اپنے رسولوں کو اور جو( لوگ ان پر) ایمان لائے ہیں ان کو بچا لیں نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ۰۰۱۰۴ گےاسی طرح ہمارے ذمہ( خود اپنا قائم کیا ہو ا)ایک حق ہے.ہم مومنوں کو (ضرور) بچا لیا کرتے ہیں.تفسیر.رُسُلَنَا بصیغہ جمع لانے کی وجہ یہاں ذکر تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا مگر فرمایا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں گے.جمع کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا ہے کہ (۱) ہر نبی سارے نبیوں کا قائم مقام ہوتا ہے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دینا گویا سب نبیوں کو نجات دینا تھا.کیونکہ اگر آپ تباہ ہوتے (نعوذباللہ) تو سب نبیوں کی صداقت مشتبہ ہوجاتی (۲) اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس امت میں آئندہ بھی رسول آئیں گے.اور وہ ہوں گے بھی امتی.کیونکہ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ میں رسولوں کی جگہ مومنون کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایک لحاظ سے رسول ہوں گے اور دوسرے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن اور امتی.قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَاۤ تو کہہ( کہ) اے لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق کسی( قسم کے) شک (و شبہ) میں ہو تو (سن لو کہ) اللہ (تعالیٰ) اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ کے سوا جن (معبودوں) کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پر ستش نہیں کرتا بلکہ میں اللہ( تعالیٰ) کی پرستش کرتا الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ١ۖۚ وَ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۰۰۱۰۵ ہوں.جوتم کو وفات دے گا اور مجھےحکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے بنوں.حلّ لُغَات.تَوَفّٰی یَتَوَفّٰی کا مادہ وَفٰی اور ماخذ وَفَاۃٌ ہے اور یہ باب تفعّل سے فعل مضارع ہے.وفات
Page 197
کے معنی موت کے ہیں اور تَوَفَّی کے معنی موت وارد کرنے اور جان نکال لینے کے ہیں.اقرب الموارد میں ہے تَوَفّی اللہُ زَیْدً اقَبَضَ رُوْحَہٗ اللہ تعالیٰ نے زید کی روح قبض کرلی یا جان نکال لی.تُوُفّیَ فُلَانٌ مَجْہُوْلًا قُبِضَتْ رُوْحُہٗ وَمَاتَ.تُوَفّی بصیغہ مجہول کے معنی ہیں اس کی جان نکال لی گئی اور وہ مر گیا.فَاللہُ الْمُتَوَفِّی وَالْعَبْدُ الْمُتَوَفّٰی.غرض اللہ تعالیٰ مُتَوَفِّی یعنی وفات دینے والا ہوتا ہے اور انسان مُتَوَفّٰی یعنی وفات پانے والا.اور قاموس میں ہے اَوْفٰی فُلَانًا حَقَّہٗ وَوَفَّاہُ وَافَاہُ فَاسْتَوْفَاہُ وَتَوَفَّاہُ وَالْوَفَاۃُ الْمَوْتُ وَتَوَفَّاہُ اللہُ قَبَضَ رُوْحَہٗ کہ جو لفظ تَوَفّی اِسْتِیْفَاء یعنی پورا پورا لینے کے معنی دیتا ہے وہ اِیْفَاءٌ تَوْفِیَۃٌ اور مُوَافَاۃٌ کا مطاوع اور لفظ وَفَّی سے ماخوذ ہوتا ہے.اور اس کا مفعول کوئی حق یا کوئی مالیت ہوتی ہے.اور جس لفظ تَوَفّی کے معنی قبض روح کے ہوتے ہیں وہ لفظ وَفَاۃٌ سے ماخوذ ہوتا ہے.جس کے معنی موت کے ہیں اور تَوَفَّاہُ اللہُ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرلی.یعنی جان نکال لی.اور کلّیات ابوالبقاء میں ہے وَالْفِعْلُ مِنَ الْوَفَاۃِ یعنی یہ فعل لفظ وَفَاۃٌ سے ماخوذ ہے.جس کے معنی موت کے ہیں.تفسیر.لفظ توفی کے معنی جب اس کا فاعل اللہ مفعول ذی روح ہو تَوَفّی کا لفظ جبکہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو اور ذی روح مفعول ہو قبض روح کے سواء اور کسی معنی میں نہیں آتا.اس کی ایک مثال بھی لغت اشعار عرب اور قرآن مجید سے پیش نہیں کی جاسکتی.جب بھی تَوَفّی اللہُ زَیْدًا آئے گا اس کے معنی قَبَض رُوْحَہٗ کے ہوں گے.کسی شاعر کسی خطیب کسی مصنف نے اس کو دوسرے معنوں میں استعمال ہی نہیں کیا.جب ذی روح مفعول ہو تو اس کے معنی پورا پورا دینا نہیں ہوتے پورا حق دینا حق ہی کے متعلق آتا ہے.لفظ مومن کے معنی مومن اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے لوگ امن میں آجائیں اور وہ دنیا کو امن دینے والا ہو.اور اس کو بھی مومن کہتے ہیں کہ جو خود امن میں آجاتا ہے.اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہوجاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی سزا سے بچ جاتا ہے.یہ دین شک پیدا کرنے والا نہیں ہوسکتا اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں تیرے دین سے شک پیدا ہورہے ہیں حالانکہ میرا عمل تو اسی مذہب پر ہے اور میں شرک سے کلی طور پر بیزار ہوں اور مجھے تو اس دین سے یقین اور ایمان ہی پیدا ہورہا ہے.نہ معلوم تمہیں شک کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں.تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آرہا ہے یَتَوَفَّاکُمْ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ جس خدا پر میرا ایمان ہے وہ تمہیں ہلاک کرنے والا ہے اور اس طرح تم پر اپنی حجت تمام کرنے والا ہے.
Page 198
وَ اَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا١ۚ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ اور اس فرمان کے پہنچانے کا بھی حکم دیا ہے کہ( اے مخاطب) تو ہر کجی سے پاک ہوتے ہوئے اپنی توجہ کو ہمیشہ کے الْمُشْرِكِيْنَ۰۰۱۰۶ واسطے دین کے لئے( وقف) کر دے اور تو مشرکوں میں سے ہرگز نہ بن.حلّ لُغَات.اَقَامَ.اَقِمْ اَقَامَ سے نکلا ہے اَقَامَ الشَّیْ ءَ کے معنی ہیں اَدَامَہٗ.اسے مداومت کے ساتھ سرانجام دیا.(اقرب) وَجْہٌ اَلْوَجْہُ کے معنی منہ کے علاوہ چھ اور بھی ہیں (۱) نَفْسُ الشَّیْءِ خود چیز (۲) سَیِّدُ الْقَوْمِ قوم کا سردار (۳) اَلْجَاہُ جاہ و حشمت.(۴) اَلْجِہَۃُ طرف (۵) اَلْقَصْدُ وَالنِّیَّۃُ نیت و ارادہ (۶) اَلْمَرْضَاۃُ خوشنودی.یُقَالُ اُرِیْدُ وَجْھَکَ اَیْ رَضَاکَ.جب اُرِیْدُوَجْہَکَ کہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں تیری خوشنودی چاہتا ہوں.(اقرب) حَنِیْفٌ اَلْحَنِیْفُ اَلصَّحِیْحُ اَلْمَیْلِ اِلَی الْاِسْلَامِ الثَّابِتُ عَلَیْہِ دین اسلام کی طرف مائل ہونے اور اس پر ثابت رہنے والا وَکُلُّ مَنْ کَانَ عَلٰی دِیْنِ اِبْرَاھِیْمَ.جو حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہو.ان معنوں میں مذہبی خیالات کا دخل پایا جاتا ہے.یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معنی اسلام کے نزول کے بعد آیات قرآنیہ کی تفسیر کے اثر کے نیچے پیدا ہو گئے.اَلْمُسْتَقِیْمُ.جو ادھر ادھر ہونے والا نہ ہو (اقرب) اصل معنی اس لفظ کے یہی معلوم ہوتے ہیں.تفسیر.شرک کے معنی اس آیت میں مشرک نہ ہو، کے یہ معنی نہیں کہ تو بتوں کو نہ پوج.یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ بنا.کیونکہ حنیف بن جانے کے بعد پھر اس ہدایت کی ضروت نہیں رہتی.بلکہ چونکہ مشرک کا لفظ حنیف کے مقابلہ پر آیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تو غیراللہ کی طرف بالکل توجہ نہ کر.ورنہ محض اس فعل سے ہی تو مشرک ہو جائے گا.گویا شرک کی باریک راہوں کی طرف توجہ دلا کر ان سے بچنے کی ہدایت کی ہے.
Page 199
وَ لَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ١ۚ فَاِنْ اور تو اللہ (تعالیٰ) کے سوا( کسی چیز) کو جو تجھے نہ (کوئی) نفع پہنچاتی ہے اور نہ( کوئی) نقصان پہنچاتی ہے.نہ پکار فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ۰۰۱۰۷ اور اگر تو نے (ایسا )کیا تو اس صورت میں تو یقیناً ظالموں میں سے ہوگا.تفسیر.خدا تعالیٰ کے سوا کوئی چیز نفع یا ضرر پہنچانے پر قادر نہیں یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کو مت پکار جو نفع و ضرر کی مالک نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے وہ بالذات نفع و ضرر کا مالک نہیں.پس کسی پر توکل نہ کر.ظالم بمعنی مشرک ظالم سے مراد اس آیت میں مشرک ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ظلم کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ظلم سے مراد کبھی شرک بھی ہوتا ہے.(بخاری کتاب التفسیر زیر آیت لم یلبسوا ایمانہم بظلم) اس جگہ بھی شرک ہی مراد ہے.وَ اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ١ۚ وَ اِنْ اور اگر اللہ (تعالیٰ) تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں( ہو سکتا) اور اگر وہ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ١ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ تیرے لئےکوئی بہتری چاہے تو اس کے فضل کو روکنے والا (بھی قطعا ً)کوئی نہیں (ہو سکتا).وہ اپنے بندوں میں سے مِنْ عِبَادِهٖ١ؕ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۰۰۱۰۸ جسے پسند کرتا ہے اسے وہ (یعنی اپنا فضل )پہنچا دیتا ہے اور وہ بہت ہی بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.تفسیر.کفّا رکے شبہات کا موجب قرآن کریم نہیں ہوسکتا اس جگہ یہ بتلایا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں جو قرآن مجید کی طرف سے شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار قرآن مجید نہیں ہے.ورنہ سب سے پہلے وہ شبہات میرے دل میں پیدا ہونے چاہیے تھے.جس پر اس کا نزول ہوا ہے.لیکن مین یقین کی مضبوط
Page 200
چٹان پر کھڑا ہوں.اور مجھے کامل محبت الٰہی دی گئی ہے.میرے ذہنی افکار تیز ہو گئے ہیں.اور ہر نفع و ضرر کے متعلق غیر اللہ کا پردہ میری آنکھ پر سے اٹھ گیا ہے.گویا ماسوی اللہ میری نظروں سے غائب ہو گیا ہے.اس گندکی اصل وجہ جب میری یہ حالت ہے تو تمہارا اعتراض غلط ہے بلکہ یہ گند تمہارے اپنے پیدا کردہ ہیں.اس گند کا علاج پھر آخر پر وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ رکھ کر بتا دیا ہے کہ اگرچہ تمہارے دل گندے ہوچکے ہیں لیکن اگر تم مغفرت مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو صاف اور پاک کر دے گا اور سب گندوں کو دھو دے گا.اور تمہیں بھی ایسا ہی یقین عطا فرمائے گا.خیر و شر کی اقسام مطابق مسئلہ تقدیر اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خیر اور شر دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک خیر اور شر وہ ہوتے ہیں جو خاص ارادۂ الٰہی کے ماتحت نہیں آتے بلکہ تقدیر عام کے ماتحت آتے ہیں.قانون قدرت ان کا موجب ہوتا ہے.ایسے خیر اور شر قانونِ قدرت کے ماتحت کوشش سے آ بھی سکتے ہیں اور ٹل بھی سکتے ہیں.لیکن ایک خیر اور شر کے نزول کا موجب اللہ تعالیٰ کا خاص ارادہ ہوتا ہے.ان کے لانے کا موجب دنیوی اعمال نہیں ہوتے.بلکہ شرعی اعمال ہوتے ہیں.ایسے خیر و شر کو لانا یا ٹلانا صرف ارادہ الٰہی پر منحصر ہے.تدبیر سے نہ وہ آسکتے ہیں اور نہ ٹل سکتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرکے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ تقدیر کا ہے.آپ کی ترقیات تدبیر کے ماتحت نہیں ہیں.کہ کوئی انہیں تدبیر سے ٹلا سکے.اور ہر عقلمند غور کرکے معلوم کرسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام فضل الٰہی سے تعلق رکھتے تھے.اور اس وجہ سے آپ کے دشمنوں کی تدابیر آپ کے مقابلہ میں باوجود آپ کی تدابیر سے بہت زیادہ زبردست ہونے کے بالکل بے کار اور رائیگاں جاتی تھیں.قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ١ۚ فَمَنِ تو( ان سے) کہہ کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آگیا ہے.پس (اب) جو کوئی (اس کی اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ١ۚ وَ مَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا بتائی ہوئی )ہدایت کو اختیار کرے تو وہ اپنی جان ہی (کے فائدے )کے لئے ہدایت کو اختیار کرتا ہے.اور جو (اس
Page 201
يَضِلُّ عَلَيْهَا١ۚ وَ مَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍؕ۰۰۱۰۹ راہ سے) بھٹک جائے تو اس کا بھٹکنا (بھی) اس (کی جان) پر ہی (ایک وبال )ہو گا.اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں.حلّ لُغَات.وَکِیْلٌ.اَلْوَکِیْلُ المَوْکُوْلُ اِلَیْہِ جس کے سپرد کوئی بات کر دی جائے.وَقَدْ یَکُوْنُ لِلْجَمْعِ وَالْاُنْثٰی.یہ لفظ واحد و جمع ہر دو کے لئے اور اسی طرح مذکر و مؤنث ہر دو کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.وَیَکُوْنُ بِمَعْنٰی فَاعِلٍ اِذَا کَانَ بِمَعْنَی الْحَافِظِ اور جب اس کے معنی حافظ یعنی نگہبان کے ہوں توا س وقت اسم مفعول کے معنی میں نہیں بلکہ اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے.وُصِفَ بِہِ اللہُ تَعَالٰی اور انہی معنوں میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے.وَقِیْلَ الْکَافِیُّ الرَّازِقُ اور بعض کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے اور رازق کے ہوتے ہیں.(اقرب) تفسیر.نبی محافظ نہیں ہوتا بلکہ مبلغ ہوتا ہے فرمایا کہ تمہاری ہدایت یا گمراہی سے میرا نفع یا نقصان نہیں.کیونکہ میں تم پر محافظ کی حیثیت سے مقرر نہیں کیا گیا.اگر میں نگران اور محافظ کی حیثیت سے مقرر ہوتا تو بے شک مجھ سے گرفت ہوتی کہ تم نے ان لوگوں سے فلاں فلاں باتوں پر عمل نہ کرایا اور فلاں فلاں باتیں نہ چھڑوائیں.میں تو صرف مبلغ کی حیثیت رکھتا ہوں.وَ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَ اصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ١ۖۚ وَ هُوَ اور جو کچھ تیری طرف وحی کیا جاتا ہے تو اس کی پیروی کر اور صبر سے کام لے یہاں تک کہ اللہ( تعالیٰ) فیصلہ (صادر) خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَؒ۰۰۱۱۰ کردے.اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.صَبَرَ.صَبَرَفُلَانًا عَنِ الْاَمْرِ حَبَسَہٗ عَنْہُ فلاں شخص کو فلاں بات سے روک رکھا.صَبَرْتُ نَفْسِیْ عَلٰی کَذَاحَبَسْتُہَا میں نے فلاں بات پر ثابت قدمی دکھائی.تَقُوْلُ صَبَرْتُ عَلٰی مَا اَکْرَہُ وَصَبَرْتُ عَمَّااُحِبُّ یعنی جب صَبَرَ کا صلہ علیٰ ہو تو اس کے معنی کسی امر پر ثابت قدم رہنے کے ہوتے ہیں اور جب
Page 202
اس کا صلہ عَنْ ہو تو اس کے معنی روک دینے کے ہوتے ہیں (اقرب) تفسیر.آخر سورۃ اور ابتداء سورۃ کے مضمون کا اتحاد آخر سورۃ میں پھر سورۃ کے ابتدائی مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے.اور فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا حکم پورا ہوکر رہتا ہے.وہ جس طرح حکیم ہے اسی طرح حاکم بھی ہے.پس تو اس کلام الٰہی کی تبلیغ کرتا جا جو تجھ پر نازل ہوا ہے.اور جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو ان لوگوں کی ایذا رسانی کی برداشت کرتا جا.اور پرواہ نہ کر.فیصلہ تیرے حق میں ہونے والا ہے خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَکہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا فیصلہ تیرے بارے میں بہت اچھا صادر ہونے والا ہے.چنانچہ جب وہ فیصلہ ہوا تو دنیا دنگ رہ گئی.وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے آپ کے والہ و شیدا ہو گئے.اور سب ملک حضرت یونسؑ کی قوم کی طرح یکدم ایمان لے آیا.اور وفود کے وفود آکر آپ ؐ کی غلامی میں داخل ہو گئے.صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
Page 203
سُوْرَۃُ ھُوْدٍ مَکِّیَّۃٌ وَھِیَ مِائَۃٌ وَّ اَرْبَعَۃٌ وَّ عِشْرُوْنَ اٰیۃً دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ سورہ ہود مکّی سورۃ ہے.اور بسم اللہ کے علاوہ اس کی ایک سو چوبیس آیتیں ہیں وَ عَشَرُ رَکُوْعَاتٍ اور دس رکوع ہیں.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ(تعالیٰ) کا نا م لے کر (شروع کرتا ہوں) جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.سورہ ہود مکی ہے سورۃ ہود مکی سورۃ ہے.ابن عباس، الحسن، عکرمہ، مجاہد، قتادہ، جابر بن زید کے نزدیک یہ سورۃ سب کی سب مکی ہے.ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے سوائے ایک آیت کے اور وہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ الآیۃ ہے.مقاتل کا قول ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے.سوائے ان تین آیتوں کے.ایک آیت فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ الآیۃ دوسری آیت اُولٰٓىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ جو عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے متعلق ہے.تیسری آیت اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ١ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ١ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.جو بنہان التمار کے متعلق ہے.(بحر المحیط) سورۃ ہود کا خلاصہ مضمون اور پہلی سورۃ سے تعلق یہ سورۃ سورۃ یونس کے مضامین میں سے ایک مضمون کو تفصیلی طور پر بیان کرتی ہے.سورۃ یونس میں بیان کیا گیا تھا کہ انبیاء کی اقوام سے اللہ تعالیٰ تین طرح سے معاملہ کرتا ہے.(۱) کسی قوم کو بالکل تباہ کر دیتا ہے.(۲) کسی قوم کو بالکل چھوڑ دیتا ہے.(۳) اور کسی قوم کے ایک حصہ کو بالکل تباہ کرکے دوسرے حصہ کو بالکل بچا لیتا ہے.اس سورۃ میں اوّل الذکر امر کی تفصیل بیان کی گئی ہے.اور بتایا ہے کہ کس طرح بعض اقوام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل مٹا دیا اور ان کا نام و نشان باقی نہ رکھا اور ان کی بجائے ایک اور قوم کو کھڑا کر دیا.جو پہلی قوموں کے تسلسل میں قائم نہیں ہوئی بلکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا ایک نیا دور شروع ہوا.روحانی حیاۃ مماۃ اور نسل کا قیام اس سورۃ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بدی اور بدکاری پر نگاہ رکھتا ہے.اور اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے.اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لئے حسب ضرورت سامان پیدا کرتا رہتا ہے.اور چونکہ وہ سامان خود انسان
Page 204
کے فائدہ کے لئے ہوتے ہیں اس لئے جب وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو روحانی طورپر ہلاک ہو جاتا ہے.جس طرح کہ جسمانی غذا کے استعمال نہ کرنے پر ہلاک ہو جاتا ہے.پھر بتایا ہے کہ جس طرح ایک نسل کے مرنے سے انسان ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے بعد اور ایک نسل اس کی قائم مقام کھڑی ہوجاتی ہے.یہی حال روحانی سلسلوں کا ہے.ایک سلسلہ تباہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک اور سلسلہ کو قائم کردیتا ہے.دنیا کی ترقی بغیر دین کے قائم نہیں رہ سکتی اس سورۃ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیوی ترقی بیشک خدا سے جدا ہوکر بھی مل سکتی ہے لیکن دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے والی قومیں وہی ہوا کرتی ہیں جو دنیا کے ساتھ دین کو بھی قائم رکھتی ہیں.یعنی جو قوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.اسی کا نام قائم رہتا ہے.مومن کی کافر کے مقابلہ میں فتح پھر یہ بتایا ہے کہ مومن کافر کے مقابلہ میں کیوں جیت جاتا ہے.اور کافر مومن کے مقابلہ میں کیوں تباہ ہوتا ہے؟ اور مختلف قوموں کی مثالیں بیان کرکے بتایا ہے کہ وہ کیسی طاقتور قومیں تھیں.لیکن ہمارے بندوں کے مقابلہ میں تباہ و برباد ہو گئیں.چنانچہ اس سورۃ میں قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کا ذکر کیا ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل پر فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کیا ہے.درمیان میں حضرت ابراہیمؑ کا ذکر بھی آیا ہے.مگر ان کا ذکر اصل مقصود نہیں بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ضمنی طور پر ان کا بھی ذکر آ گیا ہے.اس کے بعد حضرت موسیٰ ؑ کے واقعات کو لیا ہے.مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بنی اسرائیل کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اس کے لحاظ سے نہیں کیا بلکہ ان کے اس تعلق کے لحاظ سے کیا ہے جو انہیں فرعون کے ساتھ تھا.اور جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم تباہ ہو گئی.نبیوں کے حالات کوبیان کرنے کا مقصد پھر یہ بتایا ہے کہ جس قوم کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو جائے اس سے مومنوں کو بچتے رہنا چاہیےکیونکہ ایسی قوم کے ساتھ شامل ہونے سے انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے.پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے.اور آپ کو بتایا ہے کہ ان نبیوں کے حالات اس لئے بیان کئے گئے ہیں کہ تا تیرے دل کو صدمہ نہ ہو کہ میری قوم تباہ ہورہی ہے.بہت سے نبیوں کے مخالفین کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے اور آخر میں مسلمانوں کی ترقیات کی طرف توجہ دلا کر مزید تسلی دی ہے.اس سورۃ میں خصوصیت کے ساتھ آنے والے عذاب اور آنحضرت ؐ کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے اس سورۃ میں اتنے عذابوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شَیَّبَتْنِیْ ھُوْدُ(جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن سورۃ الواقعۃ) کہ سورئہ ہود نے مجھے بوڑھا کر
Page 205
دیا ہے.یعنی اس کے مضامین کا اثر مجھ پر اتنا پڑا ہے کہ اس کے نازل ہونے کے بعد میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرنے لگا ہوں.الٓرٰ١۫ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ الر (یہ) ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے اورنیز انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے.(اور یہ) حَكِيْمٍ خَبِيْرٍۙ۰۰۲ ایک حکیم اور خبیر (ہستی )کی طرف سے ہے.حلّ لُغَات.اُحْکِمَ اَحْکَمَتْہُ التَّجَارِبُ جَعَلَتْہُ حَکِیْمًـا تجارب نے اسے حکیم بنا دیا.اَحْکَمَ السَّفِیْہُ اَخَذَ عَلَی یَدِہٖ مال کی قدروقیمت نہ سمجھنے والے پر مال کے خرچ کرنے میں بندش ڈال دی.اَوْبَصَّرَہٗ مَاھُوَ عَلَیْہِ یا یہ کہ اس کی حالت پر اسے آگاہ کیا.اَحْکَمَ الشَّیْءَ اَتْقَنَہٗ.پختہ اور مضبوط کر دیا.اَحْکَمَ فُلَانًا عَنِ الْاَمْرِ رَجَّعَہٗ.ہٹا دیا.رد کر دیا.اَحْکَمَ الْفَرَسَ جَعَلَ لِلجَامِہٖ حَکَمَۃً (اقرب) گھوڑے کے لگام میں اس کا آہنی پرزہ ڈالا.تَفْصِیْلُ فَصَّلَ الشَّیْءَ جَعَلَہٗ فُصُوْلًا مُتَـمَایِزَۃً اسے جداجدا حصوں میں تقسیم کیا.فَصَلَ الثَّوْبَ قَطَعَہٗ بِقَصْدِ خِیَاطَتِہٖ.سلائی کے لئے کپڑے کو کاٹا.فَصَلَ الْکَلَامَ بَیَّنَہٗ و.ضِدُّاَ جْمَلَہٗ.کھول دیا.مجمل نہ رہنے دیا.فَصَلَ الْعِقْدَ جَعَلَ بَیْنَ کُلِّ خَرَزَتَیْنِ مِنْ لَوْنٍ وَاحِدٍ خَرَزَۃً اَوْمَرْجَانَۃً اَوْشَذْرَۃً اَوْجَوْھَرَۃً مُخَالِفَۃً لَھُمَا (اقرب) موتیوں وغیرہ کے ہار کے ہمرنگ منکوں کے درمیان کسی دوسرے رنگ کے مرجان یا جواہرات وغیرہ کے منکے ڈالے.خَبِیْرٌ اَلْخَبِیْرُ الْعَارِفُ بِالْخَبَرِ.خبر کو اچھی طرح سے جاننے والا.اور خبر کے معنی ہیں مَایُنْقَلُ وَیُتَحَدَّثُ بِہٖ.(اقرب) جس کو نقل کیا جائے.یا جس کا تذکرہ کیا جائے.یعنی ایسا امر جس سے دوسروں کے لئے دلچسپی کی وجہ موجود ہو.وَاللہُ خَبِیْرٌ.اَیْ عَالِمٌ بِاَخْبَارِ اَعْمَالِکُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہے.وَقِیْلَ عَالِمُ بِبَوَاطِنِ اُمُوْرِکُمْ یعنی بعض نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندرونی حالات سے واقف ہے.خَبِیْرٌ بمعنی مُخْبِرٌ بھی آتا ہے یعنی خبر دینے والا (مفردات)
Page 206
تفسیر.حکمت آیات کے معنی فرماتا ہے کہ اس کتاب کی آیتیں اپنے اندر حکمت رکھتی ہیں.اور جو کچھ بھی اس میں بیان ہوا ہے وہ بدی سے روکنے والا اور نیکی کی طرف لے جانے والا ہے.اور انسان کی پوشیدہ بدیوں سے اس کو آگاہ کرکے اس کی حقیقت سے اسے واقف کرتا ہے.اور اس کلام میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں اور نہ کوئی ضرورت سے زائد بات ہے.غرض تمام ضروری تعلیم بغیر فضول و لغو کے بقدر حاجت بیان کی گئی ہے.اور ساتھ ہی پھر اس امر کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ ہر اک قسم کی ضروری تفصیل بھی آگئی ہے.اور فروعات کو بھی نظرانداز نہیں کیا گیا.بلکہ بقدر ضرورت انہیں بھی بیان کیا گیا ہے.تشابہت کی بجائے فُصِّلَتْ فُصِّلَتْ سے درحقیقت متشابہ تعلیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ (آل عمران:۸) اس سورہ آل عمران کی آیت میں محکم کے مقابلہ میں متشابہ کو رکھا ہے.لیکن آیت زیرتفسیر میں متشابہات کی جگہ فصلت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.پس ظاہر ہے کہ یہ لفظ متشابہ کے معنوں کو واضح کرتا ہے.اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متشابہ درحقیقت تفصیلی تعلیم کا ہی نام ہے اور یہی تعلیم ہے جس پر اعتراض کی دشمن کو جرأت ہوتی ہے.ورنہ محکم یعنی اصولی تعلیم پر کوئی شخص حرف گیری نہیں کرسکتا.مگر حق کے معلوم کرنے کا طریق یہی ہے کہ انسان تفصیلی تعلیم کو محکم کے ماتحت لاکر دیکھے اگر وہ اس کے ماتحت آجائے تو پھر اس پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں جیسے کہ مثلاً بعض لوگ اسلام کی بعض تفصیلی تعلیمات پر جو سزا کے متعلق ہیں اعتراض کرتے ہیں.لیکن اگر وہ اسلام کی اصولی تعلیم کو دیکھیں جو یہ ہے کہ جس جگہ رحم سے فائدہ ہوتا ہو رحم کرو.اور جس جگہ سزا سے وہاں سزا دو.تو اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا.اب اگر وہ تفصیلی تعلیم کو دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے سزا کے موقع پر سزا تجویز کی ہے اور رحم کے موقعہ پر رحم.اس لئے اس پر اعتراض خلاف اصول ہے.مثلاً بعض حالات میں جنگ کی اجازت دی ہے اور یہ بات بظاہر معیوب نظر آتی ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جنگ بعض اوقات عدل و انصاف کے قیام کے لئے ضروری ہوتی ہے.پس اس پر اعتراض درست نہیں ہوسکتا.اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر کسی کا دانت نکالتا ہے جو بظاہر ظالمانہ فعل نظر آتا ہے اور رحم کے خلاف لیکن اگر حقیقت پر نظر کریں تو وہ عین رحم ہے اور آرام کا موجب.مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ سے یہ بتایا ہے کہ اس کا منبع بھی اعلیٰ ہے.اس لئے اس کی تمام تفاصیل پر اعتبار کیا جاسکتا ہے.لفظ حَکِیْممیں اس کتاب کی پُرحکمت تعلیم کی طرف اشارہ ہے حَکِیْم اسے کہتے ہیں جو موقع
Page 207
کے مطابق کام کرنے والا ہو.اس صفت سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کلام کی بھیجنے والی ہستی کے یہ مدنظر نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں شہرت یا عزت حاصل کرے بلکہ اس کے مدنظر بنی نوع انسان کا فائدہ ہے.پس اس نے کوئی ایسی تعلیم اس میں نہیں دی جو بظاہر خوبصورت ہو لیکن بہ باطن خراب ہو.بلکہ اس نے ہر وہ تعلیم جو انسان کے فائدہ کی ہے پیش کردی ہے.خواہ لوگ اس سے کس قدر ہی کیوں نہ بھاگیں اور برا نہ منائیں.ظاہر میں اچھی اور باطن میں بری تعلیم کی مثال انجیل کی تعلیم ہے.کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تھپڑ مارے تو تو دوسری بھی پھیردے(لوقا باب ۶ آیت ۲۹).اور بظاہر بری لیکن حقیقت میں اچھی تعلیم کی مثال قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے کہ جو اقوام جبراً مذہب میں دخل دیں ان کا سختی سے مقابلہ کرنا چاہیے.جس تعلیم کی غرض لوگوں میں قبولیت حاصل کرنا ہوگی.وہ اول الذکر قسم کی تعلیموں پر انحصار کرے گی.اور جس کی غرض اصلاح ہوگی وہ لوگوں کی پسندیدگی یا عدم پسندیدگی کا خیال کئے بغیر جو مفید باتیں ہیں انہیں بیان کردے گی.چونکہ اس سورۃ میں سزاؤں کا اکثر ذکر ہے اس لئے اس کی پیش بندی کرتے ہوئے سورۃ کے شروع میں ہی اپنی صفت حکیم کا ذکر کر دیا ہے.یعنی وہ سزائیں ہماری صفتِ حکیم کے ماتحت تھیں.ظلم کے ماتحت نہیں تھیں.لفظ خَبِیْرٌ کےمعنی خَبِیْرٌ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت امر سے واقف ہے.خَبِیْرٌ کا لفظ اصل حال کی واقفیت پر دلالت کرتا ہے.اور بواطن امور کے جاننے کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے.اور اس لفظ سے اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اس صفت کا مالک اندرونی تغیرات پر خاموش نہیں رہ سکتا.اور بداعمالی کی سزا کو نظرانداز نہیں کرسکتا.اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ١ؕ اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌۙ۰۰۳ اس تعلیم پر مشتمل ہے کہ تم اللہ (تعالیٰ) کے سوا ئے(کسی) کی عبادت نہ کرو.میں اس کی طرف سے یقیناً یقیناً تمہارے لئے ہوشیار کرنے والا اور بشارت دینے والا (بنا کر بھیجا گیا )ہوں.تفسیر.اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے بظاہر یہ تعلیم کہ خدا تعالیٰ نے بندہ کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے خودغرضانہ معلوم دیتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بندہ کی عبادت کا محتاج ہے.لیکن اگر قرآن پر غور کیا جائے تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے.کیونکہ قرآن کریم بوضاحت بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت کا محتاج نہیں ہے.چنانچہ سورۂ عنکبوت رکوع اول میں ہےوَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا
Page 208
يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ(العنکبوت :۸).یعنی جو شخص کسی قسم کی جدوجہد روحانی ترقیات کے لئے کرتا ہے وہ خود اپنے نفس کے فائدے کے لئے ایسا کرتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات اور ان کے ہر قسم کے افعال سے غنی ہوتا ہے.اسی طرح سورۃ حجرات میں فرماتا ہے.قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ١ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ.(الحجرات :۱۸) یعنی مذہب اسلام کو قبول کرکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں.نہ خدا تعالیٰ پر ہے.بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے وہ طریق بتایا جو لوگوں کی ترقی اور کامیابی کا موجب ہے.پس عبادت قرآن کریم کے رو سے خود بندہ کے فائدہ کے لئے ہے اور اس کی یہ وجہ ہے کہ عبادت چند ظاہری حرکات کا نام نہیں ہے بلکہ ان تمام ظاہری اور باطنی کوششوں کا نام ہے جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنادیتی ہیں.کیونکہ عبد کے معنی اصل میں کسی کے نقش کے قبول کرنے اور پورے طور پر اس کے منشاء کے ماتحت چلنے کے ہوتے ہیں.اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی منشاء کے ماتحت چلے گا الٰہی صفات کو اپنے اندر پیدا کرلے گا اور ترقی کے اعلیٰ مدارج کو حاصل کرلے گا تو یہ امر خود اس کے لئے نفع رساں ہوگا.نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے.بائیبل میں جو یہ لکھا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پر پیدا کیا.(پیدائش باب۱) تو درحقیقت اس میں بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرسکے.ورنہ اللہ تعالیٰ تمام شکلوں سے پاک ہے.پس عبادت پر زور دینے کے محض یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو.کیونکہ کامل تصویر تبھی کھینچی جاسکتی ہے جب اس وجود کا نقشہ ذہن میں موجود ہو.جس کی تصویر لینی ہو.اور عبادت اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھنے اور ان کا نقش اپنے ذہن پر جمانے کا ہی نام ہے جس میں انسان کا فائدہ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا.حدیث میں اس حقیقت کی طرف اشارہ اس مضمون کی طرف ایک حدیث میں بھی اشارہ ہے جس میں بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مَاالْاِحْسَانُ.کامل عبادت کیا ہے.تو آپ نے فرمایا کہ اَنْ تَعْبُدَاللہَ کَاَنَّکَ تَرَاہُ (بخاری کتاب الایمان باب سوال النبی ؐ عن الایمان والاسلام والاحسان والعلم الساعۃ وبیان النبی).تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا معنوی طور پر وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہو جائے.انذار کے معنی انذار کے معنی اس قسم کا ڈرانا نہیں ہوتا جیسے سانپوں یا شیروں سے ڈرایا جاتا ہے.اس قسم کے ڈرانے کو تَرْہِیْب یا تَخْوِیف کہتے ہیں.انذار لغت میں ہوشیار کرنے کے معنوں میں آتا ہے.پس مطلب یہ نہیں
Page 209
کہ میں تمہیں خدا تعالیٰ سے ڈراتا ہوں بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں تاکہ اپنے نفع کے پہلوؤں کو بھول نہ جاؤ اور نقصان کے پہلوؤں کو اختیار نہ کرلو.بشیر کے معنی اسی طرح بَشِیْرٌ کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں صرف تمہیں ہوشیار ہی نہیں کرتا بلکہ تمہاری ترقی کے سامان بھی ساتھ لایا ہوں.وَّ اَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو (اور) پھر اس کی طرف (سچا )رجوع کرو.(تب )وہ تمہیں ایک مقررہ میعاد حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ١ؕ تک اچھی طرح سےسامان عطاکرے گا.اور نیز ہرایک فضیلت والے (شخص) کو اپنا فضل عطا کرے گا.اور وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ۰۰۴ اگر تم پھر جاؤ گے.تو میں یقیناً تم پرایک بڑے (ہولناک) دن کے عذاب (کے آنے) سے ڈرتاہوں.حلّ لُغَات.مَتَاعٌ الْمَتَاعُ کُلُّ مَا یُنْتَفَعُ بِہٖ مِنَ الْحَوَائِـجِ کَالطَّعَامِ وَالْبَزِوَاَثَاثِ الْبَیْتِ وَ الْاَدَوَاتِ وَالسِّلَعِ.مَتَاعٌ عام ضروریات کی چیزوں کو کہتے ہیں جیسے خوراک، پوشاک، گھر کے استعمال کا سامان آلات اور اجناس.وَقَالَ فِی الکُلِّیَّاتِ اَلْمَتاَعُ وَالْمُتْعَۃُ مَایُنْتَفَعُ بِہٖ اِنْتِفَاعًا قَلِیْلًا غَیْرُبَاقٍ بَلْ یَنْقَضِیْ عَنْ قَرِیْبٍ.اور کلیات ابوالبقاء میں لکھا ہے کہ متاع یا متعہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو محض وقتی طور پر کچھ فائدہ پہنچانے والی ہو.وَاَصْلُ الْمَتَاعِ مَایُتَبَلَّغُ بِہٖ مِنَ الزَّادِ.اور اس کے اصل معنی زادراہ کے ہیں.وَیَأْتِی الْمَتَاعُ اِسْمًا بِمَعْنَی التَّمْتِیْعِ.اور یہ لفظ اسم مصدر کے طور پر تَمْتِیْع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے.یعنی سامانِ دنیا.(اقرب) تفسیر.استغفار کے معنی اور اس کی ضرورت پہلی آیت میں اس مقصد عظیم کی طرف توجہ دلائی تھی جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے.لیکن چونکہ مقصد تک پہنچنے میں بعض دفعہ انسان کے راستہ میں روکیں حائل ہوجاتی ہیں اس لئے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے یگانگت پیدا کرنا چاہتے ہو اور تمہارے رستہ میں ایسی رکاوٹیں ہیں
Page 210
کہ جن کی وجہ سے خدا تک پہنچنا تمہارے لئے ناممکن ہو گیا ہے تو ان کو دور کرنے کا یہ طریق ہے کہ پہلے تم اپنے رب سے غفران مانگو.یعنی گناہوں کی وجہ سے جو تمہارے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں اور وہ خدا تک تمہیں نہیں پہنچنے دیتے ان کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی اعانت طلب کرو.اور اس سے دعائیں کرو کہ وہ تمہارے زنگوں کو دور کردے.دوسرے معنی استغفار کے دبادینے کے ہیں.ان معنوں کے رو سے اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ان جذبات کے دبانے کی دعا مانگو جو خدا تک پہنچنے میں روک بن جاتے ہیں.پھر اس کے بعد فرمایا ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَیْہِ.یعنی جب وہ جذبات دب جائیں تو اس کے بعد خدا کی محبت پیدا کرنے کے لئے اس کی طرف توجہ کرو.اس طرح خدا تک پہنچنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا.اس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جذبات جب مٹ جائیں تب اس کی طرف انسان جاسکتا ہے.بغیر ایسے جذبات کے دبانے اور پرانے اثر کے مٹانے کے خدا کی کامل محبت نہیں پیدا ہوسکتی.اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ کا مقام استغفار کے بعد کا مقام ہے.وہ نادان جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلامی توبہ گناہوں کی زیادتی کا موجب ہے وہ دراصل اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں کیونکہ جو شخص گناہوں کے پچھلے اثر کے مٹانے اور جذبات کو دبانے میں لگا ہوا ہوگا اور اس کام سے فارغ ہوکر توبہ کی طرف توجہ کرے گا اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ صرف منہ سے توبہ توبہ کرے گا بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ توبہ منہ سے توبہ توبہ کرنے کا نام نہیں بلکہ گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بہ تمام توجہ جھک جانے کا نام ہے اور اگر اس فعل سے خدا نہیں ملے گا تو اور کس چیز سے ملے گا؟ مَتَاع اور اَجلِ مسمّٰی سے مراد يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا سے بتایا ہے کہ اگر تم نبی کی بات مان لو گے تو دنیوی منافع بھی ملیں گے.کیونکہ متاع عارضی نفع کو کہتے ہیں اور عارضی نفع سے مراد دنیا کا نفع ہے.اور اَجَلٍ مُّسَمًّى سے مراد وہ زمانہ ہے جو نبی کی امت کے قیام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو.فضل سے مراد وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ سے مراد دینی برکات ہیں.خواہ اس دنیا میں ملیں خواہ اگلے جہان میں.کبیر کے معنی کبیر کسی چیزکو بلحاظ وسعت کے بھی کہتے ہیں.اور بلحاظ اس کی گرانی کے بھی.پس مراد یہ ہے کہ اس تعلیم کو چھوڑ کر تم ایک لمبے عذاب میں مبتلا ہو جاؤگے.جو ہوگا بھی ایسا سخت کہ اس کا برداشت کرنا مشکل ہوگا.
Page 211
اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ١ۚ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۰۰۵ اللہ (تعالیٰ) کی طرف تم (سب) کو واپس لوٹنا ہے.اور وہ ہر چیز پر کامل طور پر قدرت رکھنے والا ہے.تفسیر.یعنی آخر اس سے معاملہ پڑنا ہے.پھر کیوں اس کی ملاقات کی تیاری نہیں کرتے؟ دوسرے وہ ہر اک امر پر قادر ہے.یعنی سزا پر بھی اور انعام پر بھی.پھر کیوں اس کے انعام کے حصول کی کوشش نہیں کرتے؟ اَلَاۤ اِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ١ؕ اَلَا سنو !وہ یقیناً اپنے سینوں کو اس لئے موڑتے رہتے ہیں کہ اس سے چھپےرہیں.سنو! جس وقت وہ اپنے کپڑے حِيْنَ يَسْتَغْشُوْنَ ثِيَابَهُمْ١ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا اوڑھتےہیں( تو اس وقت بھی) جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے وہ جانتا (ہوتا) ہے وہ یقیناً يُعْلِنُوْنَ١ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ۰۰۶ سینوں کی باتوں کو (بھی) خوب جانتاہے.حلّ لُغَات.ثَنَی ثَنَی الشَّیْءَ ثَنْیًا.عَطَفَہٗ.اس کو موڑ دیا.چکر دیا.(اقرب) تھیلے کا منہ موڑنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس میں سے باہر نہ نکلے.پس استعارۃً اس کے یہ معنی ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دلی خیالات ظاہر نہ ہوں.اِسْتِغْشَاءٌ اِسْتَغْشٰی ثَوْبَہٗ.وَبِثَوْبِہٖ اِسْتِغْشَاءً تَغَطّٰی بِہٖ.کپڑے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپ لیا اور محاورہ ہے کہ اِسْتَغْشِ ثَوْبَکَ کَیْ لَایُسْمَعُ وَلَا یُرٰی.اپنا کپڑا اوڑھ لے کہ نہ کچھ دیکھے نہ کچھ سنے.(اقرب) یہ محاورہ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوشش کرے کہ میں دوسرے کی بات نہ سنوں نہ اس کی حالت دیکھوں.تفسیر.کفار کی ہدایت سے محرومی کے اسباب اس جگہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی دو حالتوں کا ذکر کیا ہے جو انہیں ہدایت سے محروم کررہی ہیں.اول یہ کہ وہ اپنے خیالات کو چھپاتے ہیں اور انہیں ظاہر ہونے نہیں
Page 212
دیتے اس وجہ سے ان کا ازالہ نہیں ہوسکتا.ہدایت کے لئے ضروری ہے کہ انسان ان امور کو بیان کرے جو اس کے لئے صداقت کو قبول کرنے میں اصل روک ہیں.کیونکہ جب تک اصل روک دور نہ ہو ہدایت نہیں مل سکتی.یہ عیب اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ کسی مسئلہ پر بحث کرتے وقت وہ اس کے متعلق جو اصل روک ہوتی ہے اسے توظاہر نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی بحثیں کرتے رہتے ہیں.اس وجہ سے ان بحثوں کے ختم ہونے پر بھی وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں جہاں ابتداء میں تھے.دوسری بات ان کے متعلق یہ بتائی ہے کہ یہ لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل کی حالت بھی نہ بدلے اور اس کے لئے یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ بات ہی نہیں سنتے اور جو یہ کوشش کرے گا کہ بات ہی نہ سنوں وہ ہدایت کس طرح پائے گا.یہ مرض پہلی مرض سے بھی زیادہ سخت ہے.اپنی حالت کو قائم رکھنے کے لئے اکثر لوگ صداقت کے ظاہری آثار سے متاثر ہوکر اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نہ دین کی باتوں کو خود سنیں اور نہ ان کے دوست سنیں.انہیں بھی یہ کہہ کر روکتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ جادو کردیتے ہیں.ان کی باتوں کو نہ سنو.حالانکہ جب تک انسان کوئی بات سنے گا نہیں ہدایت کس طرح پاسکے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا واسطہ عالم الغیب ہستی سے ہے.کیا اس حالت میں انہیں یہ عذر کام دے سکتا ہے کہ ہم پر حجت پوری نہیں ہوئی؟ جو کوشش کرتا ہے کہ مجھ پر حجت پوری نہ ہو.اس پر حجت پوری ہوچکی اور وہ عدم علم یا عدم تسلی کا عذر نہیں پیش کرسکتا.عذر وہی پیش کرسکتا ہے کہ جو اپنی طرف سے سمجھنے کی پوری کوشش کرچکتا ہے یا وہ لوگ پیش کرسکتے ہیں جن تک ان کی اپنی کوشش کے باوجود بات نہ پہنچی ہو.یہ بھی مراد ہے کہ ان کی پوشیدہ عداوتوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور ظاہر کو بھی.ذَاتِ الصُّدور سے مراد ذَاتِ الصَّدُوْرِ سے مراد دلی خیالات اور ارادے ہیں کیونکہ صدر سے مراد اعلیٰ چیز ہوتی ہے اور انسان کے جسم میں سب سے بلند مقام اس کے ارادوں اور اس کے خیالات کو حاصل ہے کیونکہ انہی کے ماتحت اس کے اعمال ہوتے ہیں.اس میں یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کی قلبی کیفیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے.اور اسی کا اندازہ لگا کرا س نے اپنا مامور بھیجا ہے.پس ان کا یہ دعویٰ فضول ہے کہ ہمیں کسی مصلح کی کیا ضرورت ہے؟ ترتیب اس آیت کا تعلق پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں ترقیات روحانیہ کا گر بتایا تھا اور ان روکوں کا ذکر کیا تھا جو بلاارادہ انسان کے راستہ میں آجاتی ہیں اور ان کے دور کرنے کا ذکر کیا تھا.اس آیت میں ان روکوں کا ذکر کیا ہے جو انسان خود اپنے لئے پیدا کرلیتا ہے اور جن کا دور کرنا خود اس کے ارادہ اور کوشش سے متعلق ہے.
Page 213
وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ اور زمین میں ایساکوئی بھی جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ (تعالیٰ) کے ذمہ نہ ہو.اور وہ اس کی قرار گاہ کو اور اس کی مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا١ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ۰۰۷ حفاظت کی جگہ کو جانتا ہے.(یہ)سب (کچھ) ایک واضح کر دینے والی کتاب میں (موجود) ہے.حلّ لُغات.الدَّ آ بَّۃُ اَلدَّآبَّۃُ مَادَبَّ مِنَ الْحَیَوَانِ.ہر حیوان جو زمین پر چلتا ہے اسے دابۃ کہتے ہیں.وَغَلَبَ اِسْتِعْمَالُھَا عَلٰی مَا یُرْکَبُ وَیُحْمَلُ عَلَیْہِ الْأَحْمَالُ وَالْھَاءُ فِیْھَا لِلْوَحْدَۃِ کَمَا فِی الْحَمَامَۃِ.اور اس کا استعمال اکثر ان جانوروں کے لئے ہوتا ہے جن پر سواری کی جاتی ہے یا بوجھ لادا جاتا ہے وَیَقَعُ عَلَی الْمُذَکّرِوَ الْمُؤَنَّثِ.اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.اور اس کے آخر میں جو ہَا ہے یہ مفرد کی ہے نہ کہ مونث کی.جس طرح حَمَامَۃٌ (کبوتر وغیرہ) میں ھَا مفرد کے لئے اور اس لفظ کی جمع دَوَآبُّ آتی ہے.(اقرب) مُسْتَقَرٌّ.اَلْمُسْتَقَرُّ مَوْضِعُ الْاِسْتَقْرَارِ.قرار پکڑنے کی جگہ وَالشَّمْسُ تَجْرِیْ لِمُسْتَقَرٍّلَھَا اَیْ لِمَکَانٍ لَاتُجَاوِزُہ وَقْتًا وَ مَحَلًّا.یعنی وہ جگہ یا وقت جس سے سورج آگے نہیں نکل سکتا.اَلنِّہَایَۃُ وَالْغَایَۃُانتہاء اور منزل مقصود.(اقرب) مُسْتَوْدَعٌ اِسْتَوْدَعَ مَالًا.اِسْتَحْفَظَہٗ اِیَّاہُ.حفاظت کے لئے مال اس کو دیا.یعنی اس کے پاس رکھا.المُسْتَوْدَعُ مَکَانُ الْوَدِیْعَۃِ وَالْحِفْظِ.وہ جگہ جس میں کوئی چیز بطور امانت و حفاظت رکھی جائے.مَکَانُ الْوَلَدِ مِنَ الْبَطْنِ پیٹ میں بچہ کی جگہ یعنی رحم مادر.(اقرب) تفسیر.اللہ تعالیٰ کی رزق رسانی یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کے لئے رزق کے سامان مہیا کرتا ہے.آگے ان کا استعمال کرنا نہ کرنا ان کے اختیار میں ہوتا ہے.زمین کے اندر کے کیڑے یا شہروں میں رہنے والے جانور یا جنگلوں کے درندے سب کے لئے سامان بہم پہنچائے ہوئے ہیں.انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس قدر کیڑے مکوڑے کہاں سے رزق حاصل کرتے ہوں گے.مگر سب کے لئے سامان موجود ہے.حتیٰ کہ بعض کیڑوں کے رزق تک سے انسان ناواقف ہے اور نہیں جانتا کہ ان کا رزق کیا ہے.انسانی کھیتی کو ہی دیکھ لو.اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جانوروں کا خیال رکھا ہے.اگر گیہوں انسان کے لئے پیدا کی ہے تو ساتھ ہی بھوسہ بھی رکھا ہے.جو
Page 214
جانوروں کے کام آتا ہے.اگر گیہوں کے دانہ سے گیہوں ہی نکلتی تو انسان شاید جانور کا خیال کم ہی رکھتا.بعض چیزیں ایسی بنادی ہیں کہ ایک کے لئے مضر اور دوسرے کے لئے نفع رساں ہوتی ہیں.کانٹے دار جھاڑیاں اور درخت اونٹوں کی غذا ہیں اور نجاست بھیڑوں کے کام آجاتی ہے.انسانی جسم میں پیدا ہونے والے کیڑوں کے لئے اسی جگہ غذا موجود ہے.غرض ہر جنس کے لئے الگ الگ قسم کی غذا ہے.حتیٰ کہ شکاری جانوروں کی غذائیں بھی مختلف ہیں.کوئی کسی قسم کا جانور کھاتا ہے کوئی کسی قسم کا.کروڑوں بلکہ اربوں قسم کے جانور مختلف اقسام کی غذائیں کھاتے ہیں.اور انسان جو قانونِ قدرت کے راز کے ظاہر کرنے کا مدعی ہے ابھی تک ان جانوروں سے بھی پورے طور پر واقف نہیں کجا یہ کہ ان کی غذاؤں سے واقف ہو.مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے غذاؤں کے سامان مقرر کر چھوڑے ہیں.مُسْتَقَرْ اور مُسْتَوْدَعْ کے ذکر سے مقصود مُسْتَقَرْ اور مُسْتَوْدَعْ کا ذکر اس لئے فرمایا کہ مُسْتَقَرْ ہمیشگی کے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں.اور مُسْتَوْدَعْ عارضی رہائش کی اور غذا وہی مہیاکرسکتا ہے جو غذا کے حاجتمند کے رہنے کی جگہ جانتا ہو.اور پھر صحیح غذا وہی مہیا کرسکتا ہے جو کسی چیز کی قوتوں کے منتہا سے واقف ہو.پس فرمایا کہ جو ہستی مُسْتَقَرْ اور مُسْتَوْدَعْ کا علم رکھے وہی غذا مہیا کرسکتی ہے اور مناسب غذا تجویز کرسکتی ہے.فِیْ کَتَابٍ مُّبِیْنٍ کے معنی كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اشیاء آپ ہی آپ نہیں ہیں.بلکہ ان کی غایت اور منزل مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ارادوں کے ماتحت مقرر کی گئی ہے.ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ نے روحانی رزق مہیا نہ کیا ہو اس آیت سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب رزق کے سامان اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتا ہے اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانوروں کی ادنیٰ سے ادنیٰ ضرورت حقہ کو پورا کرتا ہے.تو کس طرح ہوسکتا ہے کہ اس نے اس اعلیٰ مخلوق کے لئے جو پیدائش کا منتہا ہے وہ رزق مہیا نہ کیا ہو جس سے اسے دوسری مخلوقات پر فضیلت ہے.یعنی روحانی اور اخلاقی قابلیتوں کے نشوونما کے لئے کوئی تعلیم نہ دی ہو.یہ عقل کے خلاف ہے کہ جس وقت انسان ایک خون کا لوتھڑا تھا اس وقت تو اس کی ضرورتوں کو پورا کیا لیکن جب وہ کامل انسان بنا اور اسے اپنی روحانی اور اخلاقی حالتوں کی رہنمائی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا.پس یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت کے سامان پیدا کئے ہیں.آگے انسان ان سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے.رَزَّاق وہی ہو سکتا ہے جو مُسْتَقَرْ وَ مُسْتَوْدَعْ کا علم رکھتا ہو اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ
Page 215
جس کو مُسْتَقَرْ اور مُسْتَوْدَعْ کا علم نہ ہو وہ رزق بھی مہیا نہیں کرسکتا.کیونکہ جب منازل کا علم نہ ہو تو انسان تقسیم غذا میں غلطی کر جاتا ہے.یہی وجہ ہے کہ انسانی بنائی ہوئی تعلیموں میں یا تو صرف مُسْتَقَرْ کا لحاظ رکھا گیا ہے اور جسم کو اس قدر نظرانداز کر دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے روحانی ترقی سے بھی انسان محروم رہ گیا ہے کیونکہ برتن کی خرابی سے اس کے اندر پڑی ہوئی چیز بھی خراب ہو جاتی ہے اور یا پھر مُسْتَوْدَعْ کا ہی خیال رکھا گیا ہے اور جسم کی تربیت پر ہی سب زور دے دیا گیا ہے اور روح کو بھلا دیا گیا ہے.حالانکہ انسان کا اصل مقام روحانی ترقی کا مقام ہے.پس جو اصل مقصد ہے اس کا خیال نہ کرکے گویا پیدائش انسان کی غرض کو ہی باطل کر دیا گیا ہے.اور حق یہ ہے کہ انسانی عقل ان دونوں مقامات کا خیال رکھتے ہوئے صحیح غذا تجویز نہیں کرسکتی کیونکہ انسان کو قبر اور مابعدالموت کے حالات کا علم نہیں اور روحانی غذا کا تعلق اگلی دنیا کے ساتھ ہے.پس وہ اعمال اور افکار جو اگلے جہان میں کام آتے ہیں ان کو انسان خود اپنی عقل سے معلوم نہیں کرسکتا.وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّ اور وہ وہ (ذات) ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ وقتوں میں پیدا کیا ہے كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا١ؕ وَ اور اس کا عرش پانی پر ہے.تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے (کہ )تم میں سے کس کے عمل زیادہ اچھے ہیں لَىِٕنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ اور یہ یقینی امر ہے کہ اگر تو (ان سے) کہے (کہ) تم مرنے کے بعد یقیناً اٹھائے جاؤ گے تو جن لوگوں نے انکار کیا الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ۰۰۸ ہے وہ یقیناً یقیناً کہیں گے( کہ) یہ (بات) صرف ایک دھوکہ ہے.حلّ لُغَات.مَاءٌ اَلْمَآءُ جِسْمٌ رَقِیْقٌ مَائِعٌ یُشْرَبُ بِہٖ.حَیَاۃُ کُلِّ نَامٍ.مَاءٌ کے معنی پانی کے ہیں.جس پر ہرنشوونما پانے والی چیز کی زندگی کا مدار ہے.(اقرب)
Page 216
سِـحْرٌ اَلسِّحْرُکُلُّ مَا لَطُفَ مَأْخُذُہٗ وَدَقَّ.ہر وہ بات جس کی اصلیت ایک مخفی راز ہو.وَقِیْلَ اِخْرَاجُ الْبَاطِلِ فِی صُوْرَۃِ الْـحَقِّ.جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا وَاِطْلَاقُہٗ عَلٰی مَایَفْعَلُہٗ مِنَ الْـحِیَلِ حَقِیْقَۃً لُغْوِیَّۃً اور حیلوں اور چالاکیوں کے معنوں میں اس کا استعمال لغت کی رو سے اس کا اس کے حقیقی معنوں میں استعمال ہے.سَـحَرَہٗ عَمِلَ لَہُ السِّحْرَ وَخَدَعَہٗ.سَـحَرَہٗ کے معنی ہیں اپنی چالاکی سے دوسرے کو دھوکا دیا.(اقرب) تفسیر.ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ روحانی قوتوں کے نشوونما کے لئے کوئی سامان پیدا نہ کرے فرماتا ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے کس طرح تمہاری پیدائش اور ترقی کے لئے تدریجی سامان پیدا کئے ہیں.اور تدریجی طور پر ترقی دیتے دیتے آخر میں انسان کو پیدا کیا ہے.کیا اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس دنیا کی پیدائش میں اصل مقصود انسان ہی ہے؟ پھر سوچو کہ وہ اصل مقصود کیوں ہے؟ یقیناً اپنی روحانی قابلیتوں کی وجہ سے.پھر کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روحانی قابلیتوں کو نظرانداز کردے اور ان کے نشوونما کے لئے کوئی سامان پیدا نہ کرے؟ عَرْشُہٗ عَلَی الْمَآءِکے معنی كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حیاۃ کا منبع ’’مَاء‘‘ ہے.جیسے فرماتا ہے اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ.( المرسلات :۲۱) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ.خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ (الطارق:۶،۷) وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ صِهْرًا (الفرقان :۵۵) اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا١ؕ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ١ؕ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ (الانبیاء:۳۱) غرض قرآن کریم نے متواتر بتایا ہے کہ حَیَاۃ کی پیدائش ’’مَاء‘‘ سے ہے.پس كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کا ظہورحَیَاۃ کے ذریعہ سے ہوا ہے.اور اس میں کیا شبہ ہے کہ عرش یعنی صفات کاملہ کا ظہور انسان ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے جوحَیَاۃ کی آخری کڑی ہے.لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا بھی انہی معنوں کی تصدیق کرتا ہے.کیونکہ اصلی پانی پر اگر عرش رکھا ہوا ہو تو اس سے انسان کے اعمال کی آزمائش کس طرح ہوسکتی ہے.ہاں جو معنی اوپر کئے گئے ہیں ان کے رو سے دونوں فقرے بالکل مطابق ہوجاتے ہیں.خدا تعالیٰ نے جاندار اشیاء سے اپنی صفات کاملہ کے ظہور کو وابستہ کر دیا ہے.اور اس طرح وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا انسان ان صفات سے فائدہ اٹھا کر دوسرے بنی نوع انسان سے زیادہ ترقی کر جاتا ہے.انسان کو مظہر صفات الٰہیہ بننے کے لئے پیدا کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو صفات الٰہیہ کا مظہر بننے کے لئے پیدا کیا گیا ہے.کیونکہ كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ کے بعد اس
Page 217
جملہ کے بیان کے یہی معنی ہوسکتے ہیں کہ اس لئے ہم صفات کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ تم اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کرو.جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفات کا ظہور اسی لئے ہوتا ہے کہ انسان ان کی نقل کرے.انسان اللہ تعالیٰ کی حکومت سے باہر کسی طرح نہیں ہوسکتا كَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب ہماری حکومت تمہاری پیدائش کی تمام کڑیوں پر ہے تو تم ہماری حکومت سے باہر کس طرح جاسکتے ہو.پانی سے مراد کلام الٰہی دوسرے معنیكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ کے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی صفات کا ظہور کلام الٰہی سے وابستہ کیا ہوا ہے.قرآن کریم میں متعدد جگہ کلام الٰہی کو پانی سے مشابہت دی ہے.پس ہوسکتا ہے کہ اس جگہ مَآء سے مراد کلام الٰہی ہی ہو.صفات الٰہیہ کے ظہور کی کلام الٰہی سے وابستگی کی وجہ اور یہ بتایا گیا ہو کہ ہم نے کلام الٰہی سے اس لئے اپنی صفات کے ظہور کو وابستہ کیا ہے تاکہ تم کو عمل کی طرف توجہ ہو.اگر روحانی ترقیات کے ساتھ جسمانی نعمتوں کے حصول کا سلسلہ بھی نہ لگادیا جاتا تو شاید کئی لوگ روحانی ترقیات سے محروم رہ جاتے.لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سنت مقرر کردی ہے کہ كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِيْ (المجادلۃ :۲۲) میں نے یہ بات اپنے پر فرض کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول دنیا میں غالب ہوکر رہیں گے.پس کلام الٰہی جن پر نازل ہوتا ہے انہیں اور ان کی امتوں کو دنیاوی غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اس امت نے طاقت کے حصول کے بعد کلام الٰہی پر کس طرح عمل کیا.مسئلہ ارتقاء اس آیت میں اسلامی ارتقاء یعنی ایوولیوشن تھیوری بھی بیان ہوگئی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی یعنی سلسلہ حَیَاۃ پر اپنا عرش اس لئے رکھا تاکہ حیوانات میں قابلیتوں کا مقابلہ ہو اور آخر میں یہ امر ظاہر ہوجائے کہ ان میں سے کون اصل مقصود بننے کے قابل ہے.یعنی پیدائش حیاۃ کا اصل مقصد آخر میں ایک ایسے وجود کا پیدا کرنا تھا جو حیاۃ کے اعلیٰ سے اعلیٰ جلوے دکھاسکتا ہو.اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کی پیدائش مختلف ادوار حیاۃ کے آخری دور میں ہوئی ہے.پس گویا اسلام گوبند ریا کسی اور جانور سے ترقی کرکے انسان کی پیدائش تو تسلیم نہیں کرتا لیکن یہ ضرور تسلیم کرتا ہے کہ حیاۃ کی ادنیٰ حالت سے ترقی کرتے کرتے آخر میں انسانی پیدائش کا دور آیا ہے.گو اس کی پیدائش شروع سے ہی ایسے رنگ میں چلائی گئی تھی کہ اس سے انسان ہی پیدا ہونا تھا.یہ طریق پیدائش بتا رہا ہے کہ انسان کے لئے موت کے بعد دوبارہ حیات مقدر ہے وَ لَىِٕنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طریق پیدائش ہی صاف ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو موت کے
Page 218
بعد پھر دوبارہ حَیَاۃ حاصل ہو.کیونکہ اس قدر وسیع عالم کا پیدا کرنا جس میں ایک بالارادہ ہستی یعنی انسان بس سکے صاف بتا رہا ہے کہ اس کی حَیَاۃ کا کوئی خاص مقصد ہے.لیکن دوسری طرف اس دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے تو دارالابتلاء نظر آتی ہے.اور آزمائش کی جگہ عارضی ہوتی ہے.جیسے امتحان کا کمرہ مستقل رہائش کے لئے نہیں ہوا کرتا.بلکہ امتحان دینے کے وقت تک انسان اس میں ٹھہرتا ہے.پھر دارالابتلاء میں اخفاء کا پہلو غالب ہوتا ہے اور دارالجزاء میں اظہار کے پہلو کا غالب ہونا ضروری ہوتا ہے.اب چونکہ اس دنیا میں اخفاء کا پہلو غالب نظر آتا ہے حتیٰ کہ بہت لوگ خود اللہ تعالیٰ کی ہستی تک کے بھی منکر ہیں پس ان حالات سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس دارالابتلاء سے نکال کر اسے دارالجزاء میں لے جانا ضروری ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اگر تو ان کو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو ترقی دیتے دیتے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے پیدائش عالم کا مقصود بنایا ہے تو یہ اس امر کو مان لیتے ہیں (جیسے کہ دہریہ تک ایوولیوشن تھیوری کو مانتے ہیں) لیکن جب تو اس کا عقلی نتیجہ ان کے سامنے پیش کرے کہ تب تو انسانی حیاۃ کا دور اس دنیا میں ختم نہیں ہوسکتا بلکہ ضرور ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لئے ایک زندگی کو تسلیم کیا جائے تو اس کا وہ انکار کردیتے ہیں.وَ لَىِٕنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ اور یہ (بھی) قطعی امر ہے کہ اگر ہم اس عذاب کو (ایک اندازہ کی ہوئی) مدت تک ان سے پیچھے ہٹائے رکھیں تو وہ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ١ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا یقیناً یقیناً کہیں گے (کہ) کون سی بات اسے روک رہی ہے سنو جس وقت وہ ان پر آئے گا تو ان سے ہٹا یا نہیں جائے عَنْهُمْ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۠ؒ۰۰۹ گا اور جس (عذاب) پر وہ ہنسی کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا.حلّ لُغَات.اَلْاُمَّۃُ.الْاُمَّۃُ الْجَمَاعَۃُ.جماعت گروہ.اَلْجِیْلُ مِنْ کُلِّ حَیٍّ.قوم، بڑا گروہ.الطَّرِیْقَةُ طریقہ، الدِّیْنُ مذہب.اَلْحِیْنُ وقت، زمانہ، عرصہ.(اقرب) حَاقَ حَاقَ بِہٖ یَحِیْقُ حَیْقًا وَحُیُوْقًا وَحَیَقَانًا.اَحَاطَ بِہٖ اس کا احاطہ کرلیا.حَاقَ بِہِمْ الْاَمْرُ.
Page 219
لَزِمَہُمْ وَوَجَبَ عَلَیْہِمْ.بات ان کے لازم حال ہو گئی.اور ان سے چمٹ گئی.حَاقَ بِھِمْ الْعَذَابُ.نَزَلَ وَاَحَاطَ.عذاب نازل ہو گیا اور اس نے ان کا احاطہ کرلیا.(اقرب) تفسیر.لوگ دنیا کے عذابوں کے متعلق دھوکے میں ہیں فرمایا یہ لوگ جس طرح مابعد الموت کے متعلق دھوکہ میں ہیں اسی طرح دنیا کے عذابوں کے متعلق بھی دھوکہ خوردہ ہیں.اور اگر عذاب میں تاخیر ہوجائے تو اعتراض کرنے لگتے ہیں حالانکہ اگر یہ سوچتے تو یہ بات ظاہر تھی کہ دارالابتلاء تو لازماً ڈھیل کو چاہتا ہے.اگر ڈھیل نہ ہو تو پھر یہ دنیا دارالجزاء ہوجائے.دارالجزاء کے وجود کا اقرار مخالفین کے منہ سے عجیب بات ہے کہ دنیا کے لوگ ایک طرف تو دارالجزاء سے انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف انبیاء کے مقابلہ میں قطعی عذاب کا بھی مطالبہ کرتے ہیں.اور اس طرح خود ہی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک دارالجزاء کا ہونا ضروری ہے.مطالبہ عذاب سے کفار کا مقصود ہنسی ہے وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ۠ سے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عذاب کے مطالبہ سے مراد ان کی فی الواقع عذاب کا طلب کرنا نہیں بلکہ ہنسی کرنا مقصود ہے.ان کی یہ ہنسی انہیں پر الٹ کر پڑے گی اور عذاب کو فی الواقع قریب کر دے گی.وَ لَىِٕنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ١ۚ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے (کسی قسم کی) رحمت (کا مزا) چکھائیں (اور) پھر اسے اس سے ہم ہٹا لیں تووہ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ۰۰۱۰وَ لَىِٕنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ یقیناً یقیناً (اور پھر)یقیناً نہایت ناامید (اور) نہایت ناسپاس ہو جاتاہے اور اگر ہم کسی مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ١ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ ہواسے (کسی بڑی) نعمت (کا مزا) چکھائیں تو وہ یقیناً یقیناً (اور پھر) یقیناً کہنے لگتاہے کہ( اب میری )تمام تکلیفیں مجھ
Page 220
فَخُوْرٌۙ۰۰۱۱ سے دور ہو گئی ہیں یقیناً یقیناً وہ بہت ہی اترانے والا (اور) بہت ہی فخر کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.یَئِسَ.یَؤُسٌ یَئِسَ سے صیغہ مبالغہ اسم فاعل کا ہے.اور اس کے معنی ہیں قَنَطَ.نہایت درجہ کا مایوس (اقرب) کَفُورٌ کَفُوْرٌبھی صیغہ مبالغہ اسم فاعل ہے.اور اس کے معنی ہیں نہایت ناشکرگزار.چنانچہ اس پرہاء تانیث نہیں آسکتی اور اس کی مصدر کَفُوْرٌ یا کُفْرَانٌ ہے.کَفَرَ النِّعْمَۃَ.جَحَدَھَا وَسَتَرَھَا.وَھُوَضِدُّ الشُّکْرِ ناسپاسی کی.ناشکری کی.محسن کے احسان کا انکار کیا.اور اسے چھپایا.(اقرب) اَلنَّعْمَآءُ اَلْیَدُ البَیْضَآءُ الصَّالِحَۃُ روشن اور نمایاں نعمت و احسان جو مناسب وقت اور مناسب حال ہو.(اقرب) ضَرَّآءٌ اَلضَّرَّآءُاَلزَّمَانَۃُ.اپاہج ہونا یا ہوجانا.قویٰ کا معطل ہو جانا.آفت، اَلشِّدَّۃُ سختی، مصیبت، تکلیف، دکھ.اَلنَّقْصُ فِی الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ.مالی اور جانی نقصان.نَقِیْضُ السَّرَّآءِ خوشی کا عکس یعنی غم و اندوہ کی حالت.(اقرب) اَلسَّیِّئَۃُ نَقِیْضُ الْحَسَنَۃِ.سَیِّئَۃ حَسَنَۃ کی نقیض ہے (اقرب) وَالْحَسَنَۃُ یُعَبَّرُبِھَا عَنْ کُلِّ مَایَسُرُّ مِنْ نِعْمَۃٍ تَنَالُ الْاِنْسَانُ فِی نَفْسِہٖ وَبَدَنِہٖ وَاَحْوَالِہٖ.وَالسَّیِّئَۃُ تَضَادُھَا.(مفردات) حسنہ ہر ایک خوش کن نعمت کو کہتے ہیں.خواہ جان کے متعلق ہو یا جسم یا دیگر حالات کے متعلق.اور سیئہ کا لفظ اس کی ضد ہے.فَرحٌ فَرِحٌ بھی صیغہ مبالغہ اسم فاعل کا ہے.اور اس کا فعل فَرِحَ ہے.فَرِحَ الرَّجُلُ.اِنْشَرَحَ صَدْرَہٗ بِلَذَّۃٍ عَاجِلَۃٍ.کسی وقتی لذت کی وجہ سے بہت ہی خوش ہوا.بَطَرَ.اترایا.غرور میں آ گیا.(اقرب) پس فَرِحَ کے معنی ہوئے کسی وقتی لذت کی وجہ سے حد سے زیادہ خوش ہونے والا یا اترانے والا.فَـخُوْرٌ فَـخُوْرٌبھی صیغۂ مبالغہ اسم فاعل کا ہے اور فَـخَرَ سے نکلا ہے.فَخَرَ تَمَدَّحَ بِالْخِصَالِ وَبَاھٰی بِالْمُنِاقِبِ وَالْمَکَارِمِ مِنْ حَسَبٍ وَنَسَبٍ وَغَیْرُذٰلِکَ.اِمَّافِیْہِ اَوْفِی اٰبَائِہٖ اس کے معنی ہیں اپنی طرف فضائل منسوب کرکے ان پر فخر اور ناز کیا.اور اپنے منہ سے اپنی بڑائی بیان کی (اقرب).پس فَـخُوْرٌ کے معنی ہوئے اپنے فضائل و مناقب کا اظہار کرکے ان پر بہت ہی فخر اور ناز کرنے والا.
Page 221
تفسیر.خوشی یا غم کا اثر منکرین الہام سے دور جا پڑنے والے لوگوں پر یہ دونوں غلط نقطہ نگاہ اس قوم کے افراد کے ہوجاتے ہیں.جو الہام الٰہی سے دور جاپڑتی ہے.اور ایسا شخص باوجود اس بات کے دیکھنے کے کہ دنیا کے حالات ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالتا کہ کسی خاص حالت کے ماتحت یہ تبدیلی ہوئی ہوگی بلکہ جو حالت بھی پیدا ہوجاتی ہے اس کو اپنے نفس پر غالب آنے دیتا ہے.اگر تکلیف پہنچے تو ناامید ی کو اپنے اوپر غالب آنے دیتا ہے.اگر خوشی ہو تو غرور کو.اس کی یہی وجہ ہے کہ اس نے ازلی قانون کو نہیں سمجھا.یعنی یہ کہ یہ دنیادار الابتلاء ہے.اور خدا تعالیٰ انسانی دماغ کی دونوں حالتوں کا امتحان لینا چاہتا ہے.اور دیکھتا ہے کہ اس پر خوشی کا کیا اثر ہوتا ہےا ور غمی کا کیا.اور ان دونوں حالتوں میں سے گذار کر اس کی روحانی حالت کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے.لیکن ایسا شخص چونکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتا اس لئے اس پر جو حالت بھی آئے بجائے اس سے سبق حاصل کرنے کے وہ اس کو اپنے اوپر غالب آنے دیتا ہے.اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ١ؕ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ سوائے ان لوگوں کے جو صبر (اختیار) کریں اور نیک اور مناسب حال اعمال کریں یہ وہ( لوگ) ہیں جن کے لئے مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ۰۰۱۲ بخشش اور(بہت) بڑا اجر (مقدر) ہے.تفسیر.خوشی اور اندوہ کا اثر مومنوں پر یعنی مومنوں کی حالت اوپر کی حالت کے خلاف ہوتی ہے.وہ غم اور خوشی کو اپنے نفس پر غالب نہیں آنے دیتے.بلکہ غم اور خوشی کو خود اپنے تابع رکھتے ہیں.جب غم آتا ہے تو بجائے گھبرانے اور مایوس ہونے کے صبر سے کام لیتے ہیں اور بہادری سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور مخالف اسباب کو دور کرنے کے لئے ہمت سے کوشش کرتے ہیں.اور جب خوشی کے ایام آتے ہیں تو بجائے فخر کرنے اور اترانے کے وہ ان نعمتوں کے ذریعہ سے جو ان کو ملتی ہیں نیکی اور تقویٰ میں اور بھی ترقی کر جاتے ہیں اور نیک اعمال کے ذریعہ سے ان نعمتوں سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں.مومنین کے اعمال کی جزاء لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ میں مومن کی صحیح جزاء بتائی ہے.چونکہ مومن تکالیف پر صبر سے کام لیتا ہے اور تکالیف غلطیوں یا بشری کمزوریوں کے نتیجہ میں پہنچتی ہیں اس لئے اس کے صبر کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ
Page 222
غلطیوں کو معاف کرتا یا اس کی بشری کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے اور چونکہ مومن نعمت کے حصول پر اتراتا نہیں بلکہ ان نعمتوں کو نیکی میں ترقی کرنے کا ذریعہ بناتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اسے اجر کبیر دے کر اپنے فضلوں میں زیادتی کرتا ہے.فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَ ضَآىِٕقٌۢ بِهٖ پس (اب بزعم کفار) شاید تو اس (کلام) کا جو تجھ پر وحی کیا جاتا ہے کچھ حصہ (لوگوں کو پہنچانے کی بجائے) چھوڑ دینے صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ والا ہےاور تیرا سینہ اس (کلا م الٰہی) سے اس بنا پر تنگ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں (کہ) کیوں اس پر کوئی خزانہ نہیں اتارا مَلَكٌ١ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ نَذِيْرٌ١ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌؕ۰۰۱۳ گیا یا اس کےساتھ کوئی فرشتہ آیا( حالانکہ) تو صرف (ہوشیار اور) آگاہ کرنے والا ہے اور اللہ (تعالیٰ) ہر بات کا کار ساز ہے.ٍ حلّ لُغَات.لَعَلَّ لَعَلَّ طَمَعٌ وَاِشْفَاقٌ کہ لَعَلَّ طمع اور خوف ہرد وکے لئے آتا ہے.وَلَعَلَّ وَاِنْ کَانَ طَمَعًافَاِنَّ ذٰلِکَ یَقْتَضِیْ فِی کَلَامِھِمْ.تَارَۃً طَمَعَ الْمُخَاطَبِ وَتَارَۃً طَمَعَ الْمُخَاطِبِ وَتَارَۃً طَمَعَ غَیْرِھِمَا فَقَوْلُہٗ تَعَالٰی فِیْمَا ذَکَرَ عَنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَۃَ فَذٰلِکَ طَمَعٌ مِنْہُمْ وَقَوْلُہٗ فِی فِرْعَوْنَ لَعَلَّہٗ یَتَذَکَّرُ اَوْ یَخْشٰی فَاِطْمَاعُ مُوْسٰی مَعَ ھَارُوْنَ وَمَعْنَاہُ فَقُوْلَا لَہٗ قَوْلًا لَیِّنًارَاجِیَیْنِ اَنْ یَّتَذَکَّرَ اَوْ یَخْشٰی وَقَوْلَہٗ تَعَالٰی فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ بَعْضَ مَایُوْحٰی اِلَیْکَ أَیْ یَظُنُّ بِکَ النَّاسُ ذٰلِکَ.اور جب یہ لفظ طمع کے معنوں میں ہو تو عربی زبان کے محاورہ میں اس کے کئی مفہوم ہوتے ہیں.کبھی اس سے مخاطب کے دل کی طمع کا اظہار یا اس کے دل میں طمع کا پیدا کرنا مراد ہوتا ہے.کبھی مخاطب یعنی بولنے والے کی طرف سے طمع مرادہوتی ہے.اور کبھی ان دونوں کے سواء دوسروں کی طمع کا ذکر ہوتا ہے.جیسا کہ قرآن کریم میں جو فرعون کی قوم کا قول آتا ہے کہلَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ.اس میں فرعون کی قوم نے اپنی طمع کا اظہار کیا ہے کہ کیا اچھا ہو کہ یہ جیت جائیں.اور ہم ان کی اتباع کریں اور جو خدا تعالیٰ کا یہ قول فرعون کے بارہ میں آتا ہے کہلَعَلَّہُ یَتَذَکَّرُ اَوْیَخْشٰی.اس میں موسیٰ اور ہارون کو جو مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ نے طمع دلائی ہے کہ شاید فرعون ہدایت پا جائے.اور یہ جو آیت ہےلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ.اس میں دوسروں کی طمع کا ذکر ہے کہ دوسرے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید تو ان کے اعتراضوں سے ڈر کر
Page 223
خدا کے کلام کے بعض حصوں کو چھپادے.(مفردات) کَنْزٌ الْکَنْزُمَایُدَّخَرُ.جس مال کو انسان جمع کرے.اَلْمَالُ الْمَدْفُوْنُ فِی الْاَرْضِ.زمین میں گاڑا ہوا مال.اِسْمٌ لِلْمَالِ اِذَااُحْرِزَفِی وِعَاءٍ.جب مال کسی حفاظت کی چیز میں رکھا ہوا ہو تو اسے بھی کَنْزٌ کہتے ہیں.الذَّھَبَ سونا.اَلْفِضَّۃُ.چاندی.مَایُحْرَزُفِیْہِ الْمَالُ.جس چیز میں مال کو محفوظ کرکے رکھا جاوے یعنی مَخْزَن.(اقرب) تفسیر.لَعَلَّکَ تَارِکٌ تعریض کے طور پر فرمایا ہے قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ بعض جگہ سوال کا ذکر چھوڑ دیتا ہے صرف جواب دے دیتا ہے.اور اسی سے سوال سمجھ میں آجاتا ہے.اس آیت میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے.گو جس سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے اسے علیحدہ بیان نہیں کیا گیا.لیکن آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ کا وعدہ سن کر کفار نے اعتراض کیا کہ مومنوں کو تو مغفرۃ اور اجرکبیر پیچھے ملے گا پہلے تم جو سلسلہ کے بانی ہو اپنا حال تو دیکھو کہ نہ تمہارے پاس خزانہ ہے اور نہ کمزوریوں کو دور کرنے کے ظاہری مظہر فرشتے ہیں.اللہ تعالیٰ تعریضاً فرماتا ہے کہ اوہو! یہ بڑا بھاری اعتراض انہوں نے کیا ہے اس کے خوف کے مارے تو اب تو ضرور کلام الٰہی کا کچھ حصہ یعنی جس میں اسلام کی ترقیات کی پیشگوئیاں ہیں چھپا ڈالے گا.مطلب یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوسکتا.دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ اس جگہ لَعَلَّ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ دشمن یہ طمع رکھتا ہے کہ اس کے ان اعتراضوں سے ڈر کر تو کلام الٰہی کو چھپانے لگے حالانکہ اس کی یہ طمع باطل ہے.کیونکہ تو تو فقط نذیر ہے یعنی پیغامبر اور پیغامبر کا کام تو دیانت داری سے پیغام پہنچانا ہوتا ہے.اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بعض حصہ کلام کو چھپادے.اور بعض کو ظاہر کردے.پھر تیرا دعویٰ خدائی کا نہیں ہے کہ دنیا کے خزانے تیرے قبضہ میں ہوں.اگر یہ سوال کیا جائے کہ جن مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو اجر کبیر ملے گا وہ بھی تو انسان ہی ہوں گے.تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو ایک خاص وقت تک صبر کرنے کے بعد کی حالت کا ذکر ہے نہ کہ شروع سے ہی ایسا وعدہ تھا.سو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقیات کے ظاہری مظاہر کا مطالبہ بھی کفار تبھی کرسکتے تھے جب کہ وقت مقررہ آتا.نہ کہ شروع سے ہی.شروع سے طاقت کا ساتھ ہونا تو ذاتی اقتدار پر دلالت کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے نہ کہ بندہ کو.یہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌسے یہ بتایا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوکر رہے گا.تجھے مغفرت بھی ملے گی اور اجر کبیر بھی.خدا تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے جو تیرے کام کو پورا کریں گے اور اجر کبیر بھی
Page 224
ملے گا.تیرا تو کیا ذکر ہے تیرے غلام بھی بادشاہ ہوں گے ہر اک غیر متعصب انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں پوری ہوئیں یا نہیں.اسلام کی ترقیات کے راستہ سے سب روکیں ملائکہ نے دور کردیں یا نہیں.اور اس طرح مغفرۃکامل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی یا نہیں.اسی طرح کیا آپ کو اور آپ کے خدام کو جو دیر تک دنیا کے عذابوں پر صبر سے کام لیتے رہے تھے آخر اجرکبیر مل کر رہا کہ نہیں؟ آنحضرت قرآن کریم کے کسی حصہ کو چھوڑنے والے نہیں تھے افسوس ہے کہ اسلام کے دشمن اس آیۃ سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے اعتراضوں سے ڈر کر بعض حصہ قرآن کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئے تھے.حالانکہ سیاق و سباق اس آیت کا ان معنوں کو رد کررہا ہے.کیا کوئی عقلمند بھی خیال کرسکتا ہے کہ فرشتوں یا خزانہ کا مطالبہ کوئی ایسا اعتراض تھا کہ اس سے ڈر کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام الٰہی کو چھوڑنے کے لئے تیار ہوجاتے اور کیا اِنَّمَاۤ اَنْتَ نَذِيْرٌ١ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ دو ایسی باتیں ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے اوجھل تھیں یا یہ وہ باتیں ہیں جو دشمنان اسلام کی نظر سے اوجھل تھیں؟ اس آیت میں کفار کی طمع کا ذکر ہے اگر صرف کفار کی نظر سے یہ امور اوجھل تھے تو انہی کی طمع کا اس آیت میں ذکر ہے نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طمع کا.کیا معترضین یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش نے خاص وفد کے ذریعہ سے یہ درخواست کی کہ یا تو آپ ان سے سمجھوتہ کرلیں یا پھر وہ آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو پیس ڈالیں گے تو اس وقت آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر سورج کومیرے دائیں اور چاند کو بائیں لاکر کھڑا کردو تب بھی میں خدا تعالیٰ کی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتا(السیرة النبویة لابن ہشام زیر عنوان مباداۃ رسول اللہ قومہ.....).پھر کیا ان دولغو اعتراضوں سے آپ ایسے متاثر ہوسکتے تھے کہ کلام الٰہی کو چھپانے کے لئے تیار ہوجاتے؟ اگر اس سے اگلی آیت پر غور کیا جائے تو وہ بھی اسی بیہودہ خیال کی تردید کرتی ہے.کیونکہ اس میں ساری دنیا کو چیلنج دیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی کسی دس سورتوں کی مثل لے آؤ.اگر آپ کے دل میں شک ہوتا تو کیا اس کے ذکر کے ساتھ ہی یہ چیلنج دیا جاسکتا تھا؟ یہ چیلنج تو بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کریم کی صداقت کا یقین پہاڑ سے بڑھ کر راسخ تھا.
Page 225
اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ١ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ کیا وہ کہتے ہیں (کہ) اس نے اس (کتاب) کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے.تو (انہیں) کہہ کہ اگر تم (اس بیان مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ میں) سچے ہو تو اس جیسی دس سورتیں اپنے پاس سے گھڑی ہوئی (بنا) لاؤ اور اللہ (تعالیٰ) کے سوا ئےجس (کو بھی كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۰۰۱۴ اپنی مدد کے لئے لانے )کی تمہیںطاقت ہو اسے بلا لو.تفسیر.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی حقیقی خزانہ سے تہی دست نہیں ہو ئے اس آیت سے میرے ان معنوں کی جو پہلی آیت میں میں نے کئے تھے تصدیق ہو گئی.گذشتہ آیت میں ان کے اس اعتراض کے کہ اب یہ ہمارے اعتراضوں سے ڈر کر قرآن کریم کے بعض حصوں کو ضرور چھوڑ دے گا دو جواب دیئے گئے تھے.اول یہ کہ تو تو نذیر ہے تو نے خدائی کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں کہ یہ چیزیں ساتھ لانا بھی تیرا کام ہو.دوم یہ کہ تو تو پیغامبر ہے جو پیغام تجھے ملے گا تو اس کے ظاہر کرنے پر مجبور ہے.اس جواب پر کفار کی طرف سے یہ اعتراض ہوسکتا تھا کہ یہ تو صرف تمہارا دعویٰ ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو ہمارا خیال تو یہی ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی خاص طاقت نہیں تو تم مفتری ہو.سو اس اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا کہ گو ظاہری خزانے ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں.مگر باطنی خزانہ موجود ہے.اور خزانہ بھی وہ جس کے برابر ایک انسان تو کیا سب دنیا کے پاس مجموعی طور پر بھی دولت نہیں ہے.اور وہ قرآن کریم ہے.پس اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو کہ ہمارا رسول مفتری ہے اور اس کے لائے ہوئے کلام کے بعض حصے ناقص ہیں اور بدلنے کے قابل ہیں تو سارے قرآن کریم کے برابر نہیں صرف دس سورتوں کے برابر کوئی کلام پیش کردو.جو اس کے ان حصوں کی مثل ہو جن کو تم بدلنے کے قابل سمجھتے ہو اور اگر ایسے حصوں کی مثل بھی پیش نہ کرسکو جو تمہارے نزدیک ناقص ہیں اور بدلنے کے قابل ہیں تو تم کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کے پاس وہ خزانہ ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی.آیات تحدی و مطالبہ نظیر فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ.سورۂ یونس میں بتایا جاچکا ہے کہ یہ مضمون کئی جگہ آیا
Page 226
ہے.اول سورۂ بقرہ ع۳ کی آیت وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ١۪ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ہے دوم سورۂ یونس میں فرمایا ہےاَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ١ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.یونس ع۴.سوم یہ زیر تفسیر آیت ہے کہ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ١ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّ ادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.چہارم سورۂ بنی اسرائیل ع۱۰ میں آتا ہےقُلْ لَّىِٕنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.پنجم سورئہ طور ع۲ میں آیا ہےاَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ١ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ.فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖۤ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ.ان مطالبات میں مقدار مطلوبہ کے اختلاف کی وجہ ان پانچ جگہوں میں سے دو جگہ پر تو ایک ہی قسم کا مطالبہ ہے.باقی تین جگہ میں علیحدہ علیحدہ مطالبے کئے گئے ہیں.چنانچہ سورۂ بنی اسرائیل میں سارے قرآن کریم کی مثل کا مطالبہ کیا گیا ہے.اور فرمایا ہے کہ اگر سارے جن و انس بھی اکٹھے ہوجائیں تو قرآن کریم کی مثل نہیں لاسکیں گے.یہاں سورۂ ہود میں دس سورتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دس سورتیں اپنے پاس سے بنا کر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرکے شائع کرو.سورۂ بقرہ اور سورۂ یونس میں ایک سورۃ کا مطالبہ ہے.اور سورۂ طور میں ایک سورۃ کی بھی شرط نہیں ہے.خواہ وہ ایک بات ہی بنا کر لے آئیں.اب بظاہر یہ بات عجیب نظر آتی ہے کہ کہیں سارے قرآن کا مطالبہ ہے کہیں دس سورتوں کا ہے اور کہیں ایک سورۃ کااور کہیں ایک ہی بات پر اکتفاء کی گئی ہے.اور طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق کیوں ہے.بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ترتیب نزول کے لحاظ سے ایسا ہوا ہے.پہلے سارے قرآن کی مثل کا مطالبہ کیا.جب وہ نہ لاسکے تو دس سورتوں کا مطالبہ کیا.جب وہ بھی نہ لاسکے تو پھر فرمایا ایک سورۃ ہی لے آؤ.جب وہ بھی نہ لاسکے تو پھر فرمایا کہ کچھ ہی لے آؤ.خواہ ایک بات ہی ہو.اس اختلاف کا تدریجی نزول پر مبنی ہونا ثابت نہیں ہوتا میرے نزدیک اس میں کچھ اشتباہ معلوم ہوتا ہے.اس لئے کہ ان سورتوں میں سے کہ جن میں اس مضمون کا ذکر آیا ہے نزول کے لحاظ سے سب سے پہلے سورہ طور ہے اور اس میں قرآن کریم کی بجائےبِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖۤ ہے.یعنی اس جیسا کوئی کلام لے آؤ.اور شرط ایک سورۃ کی بھی نہیں رکھی گئی.خواہ وہ کلام ایک سورۃ سے بھی کم ہو.پس عقلاً یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ سورہ طور میں تو پہلے بغیر مقدار مقرر کرنے کے مثل کا مطالبہ کیا گیا ہو اور اس کے بعد سورۂ بنی اسرائیل میں پورے قرآن کا مطالبہ کیا گیا ہو اور
Page 227
بعد میں اس مطالبہ کو گرا کر دس سورتوں میں اور پھر دس سورتوں سے گرا کر ایک سورۃ میں محصور کر دیا گیا ہو.دوسرے یہ کہ یہ کوئی واقعہ تو ہے نہیں کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں بلکہ ایک چیلنج ہے جو ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے.اب ہم دنیا کے سامنے کیا پیش کریں.آیا یہ کہ سارا قرآن لاؤ یا یہ کہ دس سورتیں لاؤ یا ایک سورۃ یا ایک بات لاؤ.اگر ایک آیت کا مطالبہ کافی ہے تو ایک سورۃ کا مطالبہ کیوں کریں.اور اگر ایک سورۃ کا لانا کافی ہوسکتا ہے تو دس سورتوں کا مطالبہ کیوں کریں اور اگر دس سورتوں کا لے آنا کافی ہے تو سارے قرآن کی مثل لانے کے لئے کیوں کہیں؟ اس تحدی والی سورتوں کے زمانہ نزول کا مختلف ہونا ثابت نہیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس میں ترتیب نکالنے کی ضرورت نہیں.اول تو ان میں سے بعض سورتیں ایسے قریب قریب کے زمانہ کی نازل شدہ ہیں کہ ان کی صحیح ترتیب کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے.دوسرے قرآن کریم کی تنزیل اس طرح نہیں ہوئی کہ ایک وقت میں ایک ہی سورۃ نازل ہوئی ہو بلکہ قریب قریب نازل ہونے والی سورتیں بعض دفعہ ایک ہی وقت میں تین تین چار چار نازل ہوتی جاتی تھیں اور ان میں سے ایک کو پہلی کہنا اور دوسری کو بعد کی کہنا اس لحاظ سے تو گو درست ہو کہ ایک کی آخری آیت پہلے اور دوسری کی آخری آیت پیچھے نازل ہوئی ہو لیکن ایک کی سب آیتوں کے متعلق کہنا کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہیں اور دوسری کی سب آیتوں کے متعلق یہ کہنا کہ یہ پیچھے نازل ہوئی ہیں درست نہیں ہوسکتا.پس میرے نزدیک ان آیتوں میں ایسے مطالبات بھی ہیں جو ترتیب نزول کے حل کرنے کے محتاج نہیں ہیں اور سب کے سب ایک ہی وقت میں آج بھی اسی طرح پیش کئے جاسکتے ہیں جس طرح کہ زمانۂ نزول میں پیش کئے جاسکتے تھے.اس تحدی کے ساتھ اکثر جگہ مال و دولت اور طاقت کا بھی ذکر آیا ہے پیشتر اس کے کہ میں ان مختلف تحدیوں کی تشریح کروں جو ان آیات میں مذکور ہیں.میں اس عجیب بات کی طرف بھی توجہ پھرانی چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج جس جس جگہ آئے ہیں ان کے ساتھ ہی مال و دولت اور طاقت و قدرت کا بھی ذکر آیا ہے.سوائے سورۂ بقرہ کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نیا چیلنج نہیں ہے.بلکہ سورۂ یونس کے چیلنج کو سورہ بقرہ کے مضامین کی ضرورت کے لحاظ سے دہرایا گیا ہے (سورہ یونس مکی ہے اور سورہ بقرہ مدنی ہے)اس لئے اس میں اس ذکر کو غیرضروری سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے.اس کے سوا باقی سب سورتوں کو دیکھ لو سب میں مال و دولت یا طاقت و قدرت کا ذکر ہے.سورۂ یونس میں اس مطالبے سے چند آیات پہلے آیا ہے قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ١ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ۠ اللّٰهُ١ۚ فَقُلْ اَفَلَا
Page 228
َتَّقُوْنَ(یونس:۳۲).گویا دعویٰ کیا ہے کہ سب خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں.خواہ وہ رزق کے ہوں یا قوائے طبیعہ کے یا قوائے عملیہ کے ہوں یا مختلف قوتوں کو ایک نظام میں لانے کے متعلق ہوں.اور پھر اس کے بعد فرمایا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآىِٕكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ١ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ١ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّهْدٰى ١ۚ فَمَا لَكُمْ١۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ.(یونس:۳۵،۳۶) اس میں بھی طاقت و قوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.پھر سورۂ طور میں تحدی کے بعد فرماتا ہے اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ.اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ١ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ.اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآىِٕنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَۜيْطِرُوْنَ(الطور:۳۵ تا ۳۸).یہاں پر بھی دولت اور حکومت اور طاقت و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے.سورۂ ہود کی زیر تفسیر آیت سے پہلے بھیلَوْ لَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ(ہود:۱۳)آیا ہے.سورۂ بنی اسرائیل میں تحدی کے بعد آیا ہےوَ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا.اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا.اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ قَبِيْلًا.اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِي السَّمَآءِ(بنی اسرائیل:۹۱ تا ۹۴) اس جگہ بھی مال و دولت اور طاقت و قوت کا ہی ذکر ہے.غرض چاروں جگہ پر ایک ہی قسم کا مطالبہ بیان ہوا ہے.یا مطالبہ کا ذکر نہیں لیکن مطالبہ کا جواب دیا گیا ہے.ان تحدیوں میں مطالبہ خزائن کے جواب میں قرآن کریم کو بطور خزانہ پیش کیا گیا ہے پس معلوم ہوتا ہے کہ خزانوں کے سوال اور مطالبۂ مثل میں کوئی گہرا تعلق ہے.اور وہ یہی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو خزانہ قرار دیا ہے اور مخالفین کے خزانہ کے مطالبہ کایہ جواب دیا ہے کہ اس کا اصل خزانہ قرآن کریم ہے اور لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَیْہِ مَلَکٌ کا بھی یہی جواب دیا ہے کہ ملائکہ ظاہری مقابلوں کے لئے نہیں اترتے.بلکہ کلام الٰہی لے کر اترا کرتے ہیں.اور وہ اس پر نازل ہوچکا ہے پس یہ کہنا کہ اس پر مَلَک نہیں اترا یا یہ کہ اترنا چاہیےبے معنی قول ہے.اور ایسی چیز کا مطالبہ ہے جو پہلے سے حاصل ہے.پھر چونکہ ملائکہ کا اترنا یا روحانی خزانہ کا حصول بہ ظاہر ایک دعویٰ معلوم ہوتا ہے جس کا ثبوت نہیں اس کے لئے خود قرآن کریم کے بے مثل ہونے کو پیش کیا ہے کہ یہ اپنی صداقت کی آپ دلیل ہے اور اس کے اندر ایسے دلائل موجود ہیں جو اسے ایک لاثانی خزانہ اور منجانب اللہ کلام ثابت کرتے ہیں اور یہ جو فرق کیا ہے کہ جس جگہ زیادہ کلام کا مطالبہ ہے اس جگہ کفار کی طرف سے خزانوں یا ملک کا مطالبہ ہے اور جس جگہ تھوڑے کلام کی مثل کا مطالبہ ہے اس جگہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ کفار خزانوں کے مالک اور
Page 229
قانون قدرت کے متولی ہیں.سو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن مقامات پر پورے قرآن یا دس سورتوں کا مطالبہ ہے اس جگہ سوال ایسا ہے جو کفار کے ذہن میں آسکتا تھا اور موٹا تھا.پس ان کے سوال کو پیش کرکے اس کا جواب دے دیا گیا ہے.لیکن بعض پہلو قرآن کریم کے بے مثل ہونے کے ایسے رہ جاتے ہیں جن کے متعلق سوال کرنے کا بھی کفار کو خیال نہیں آسکتا تھا.اگر ان کا بیان کرنا بھی کفار کے سوالات پر منحصر رکھا جاتا تو وہ پہلو پوشیدہ ہی رہتے.اس لئے ان پہلوؤں کو قرآن کریم نے خود سوال پیدا کرکے بتا دیا اور اس طرح قرآن کریم کی تکمیل کے سب پہلوؤں کو روشن کر دیا.فَتَبَارَکَ اللہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ.ان تمام تحدیوں پر تفصیلی نظر اب میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک مطالبہ کو الگ الگ لے کر بتاتا ہوں کہ کس طرح ان آیات میں قرآن کریم کی مختلف خوبیوں کے مقابلہ کی دعوت دی گئی ہے.اور ہر جگہ کے مناسب حال زیادہ یا کم کلام کا مطالبہ کیا گیا ہے.سورئہ بنی اسرائیل والی تحد ی سب سے بڑا مطالبہ سارے قرآن کی مثل لانے کا ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے.اس مطالبہ میں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ جس کلام کو منکر پیش کریں اسے خدا تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کریں بلکہ جائز ہے کہ ان کا پیش کردہ کلام مفتریات میں سے نہ ہو.اور ان کا صرف یہ دعویٰ ہو کہ گو ہم نے یہ کلام خود بنایا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے لیکن یہ کلام قرآن کریم کی مثل یا اس سے بڑھ کر ہے.چونکہ مثل کی حدبندی بھی ضروری تھی کہ وہ کلام کس امر میں مثل ہو اس لئے اس کی تشریح بھی خود کردی اور فرمایا کہ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ١ٞ فَاَبٰۤى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا (بنی اسرائیل:۹۰) اس کلام میں ہر پہلو سے لوگوں کے فائدہ کے لئے ہر اک ضروری دینی امر پر روشنی ڈالی گئی ہے.لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس کے انکار پر مصر ہیں.یہی چیز ہے جس میں مثل کا مطالبہ کیا گیا ہے.اگر فی الواقع وہ اس کلام کو انسانی کلام سمجھتے ہیں تو چار خوبیوں والا کلام پیش کریں.جو اپنی خوبیوں میں قرآن کریم کے برابر ہو.قرآن کریم کی چار صفات (۱)اس میں ہر ضروری دینی مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہو.یعنی اعتقادات، فلسفۂ اعتقادات، صفات باری اور فلسفۂ ظہور صفات باری، علم کلام عبادات، فلسفۂ عبادات، علم اخلاق،فلسفۂ اخلاق، معاملات، فلسفۂ معاملات، مدنیت، اقتصادیات، سیاسیات کا جو حصہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا فلسفہ معاد اور اس کے متعلق تمام امور وغیرہ وغیرہ سب امور ضروریہ پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہو.(۲) وہ بحث جو ان امور کے متعلق کی گئی ہو سیرکن ہو نہ صرف وسعت کے رو سے احاطہ ہو یعنی سب علوم
Page 230
کے متعلق کچھ نہ کچھ بحث ہو بلکہ حق کی گہرائی کا بھی احاطہ ہو اور ہر مسئلہ کے ہر پہلو کو پیش کرکے اس میں ہدایت دی گئی ہو.(۳) وہ تمام تعلیم باوجود اپنی وسعت اور باریکی کے مضرت رساں نہ ہو.بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہو.(۴) اس میں کسی ایک قوم یا طبقہ کے فائدہ کو مدنظر نہ رکھا گیا ہو بلکہ تمام بنی نوع انسان کی فطرت کومدنظر رکھا گیا ہو.اور ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات اور ہر درجہ اور ہر فہم کے انسان کے متعلق اس میں ہدایت موجود ہو.بجائے مطالبہ کی صورت کے پیشگوئی کی صورت میں تحدی چونکہ قرآن کریم ابھی مکمل نہ ہوا تھا اس لئے یہ نہیں فرمایا کہ تم ابھی اس کی مثل لے آؤ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ نہ لاسکو گے یعنی نہ اس کی موجودہ حالت میں اور نہ اس وقت جب یہ مکمل طورپر نازل ہو جائے گا.حق یہی ہے کہ قرآن کریم نے ایسے رنگ میں روحانی امور پر بحث کی ہے کہ اوپر کے چاروں امور کے مقابلہ میں اس قدر کلام میں بھی کوئی شخص اس کی کوئی مثل نہیں لاسکتا تھا.جو اس وقت تک نازل ہوچکا تھا اور اس وقت کے لحاظ سے قرآن کہلاتا تھا.سپریچوئلزم کا ابطال اس آیت کے مطالب میں ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جس کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا.اور وہ یہ کہ اس میں علم الارواح کے ماہرین کو بھی جنہیں انگریزی میں سپریچولسٹ کہتے ہیں مخاطب کیا گیا ہے اور جن سے مراد وہی ارواح ہیں جن سے تعلق پیدا کرکے روحانیات کی باریکیاں معلوم کرنے کے علم الارواح کے علماء مدعی ہیں اور بتایا ہے کہ قرآن کریم کی مثل نہ تو انسان خود لا سکتے ہیں اور نہ پوشیدہ ارواح کی مدد سے لا سکتے ہیں.جن کی مدد کا ان کو دعویٰ ہے.اس جگہ جن سے مراد وہ جنات نہیں کہ جو عوام الناس میں مشہور ہیں کیونکہ ان کی مدد سے کلام لانے کا مطالبہ ایک مہمل بات ہوجاتی ہے.نیز اس آیت سے پہلے وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ١ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِرَبِّيْ بھی مذکور ہے.جس سے ظاہر ہے کہ اس جگہ ارواح کا ہی ذکر ہے نہ کہ جنات کا.(تفصیل کے لئے دیکھو اس آیت کی تفسیر بنی اسرائیل رکوع ۱۰ میں) دس سورتوں کا مطالبہ دوسری آیت جس میں کفار کا اعتراض بیان کیا ہے کہ اس کے پاس خزانہ اور ملک نہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو تم دس سورتیں مفتریات کی اس کے مقابلہ میں لے آؤ.پس اس جگہ سورتوں کو بطور خزانہ کے پیش کیا اور مفتریات کا مطالبہ کرکے بتایا ہے کہ اگر اس کا دعویٰ وَحی بالملائکہ کا جھوٹا ہے اور اس کے ساتھ ملائکہ نہیں آئے تو تم بھی زیادہ نہیں تو دس سورتیں ایسی پیش کردو جن کے متعلق یہ دعویٰ ہوکہ ملائکہ نے
Page 231
باذن الٰہی ہم پر اتاری ہیں.پھر دیکھو! کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے؟ اور اگر تم میں یہ جرأت نہیں کہ تم ایسا جھوٹا دعویٰ کرسکو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کس طرح خیال کرسکتے ہو کہ اس قدر افترا کررہا ہے.اور اگر افترا کررہا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ کیوں ہے؟ دس سورتوں کا مطالبہ کفار کی لَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ والی طمع کے جواب میں ہے غرض اس جگہ عقلی مقابلہ کے ساتھ آسمانی مقابلہ کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ جو اس جگہ فرمایا کہ دس سورتیں ایسی لاؤ اس کی یہ وجہ ہے کہ اس جگہ قرآن کریم کے ہر رنگ میں مکمل ہونے کا دعویٰ نہ تھا بلکہ کلام بعض القرآن کے متعلق تھا.یعنی مخالف معترض تھا کہ اس کے بعض حصے قابل اعتراض ہیں جیسا کہ آیت فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ سے ظاہر ہے اور اسی طرح کفار کے اس سوال سے بھی ظاہر ہے کہ اس کے پاس خزانہ اور ملک نہیں.پس اس جگہ سارے قرآن کے مقابلہ کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم قرآن میں جو بھی کمزور سے کمزور حصہ سمجھتے ہو اس کے مقابلہ میں دس سورتیں بنا کر پیش کردو تا تمہارے دعوے کی آزمائش ہو جائے.دس کا عدد اختیار کرنے کی وجہ دس کا عدد اس واسطے استعمال کیا کہ یہ عدد کامل ہے اور چونکہ معترض کے دعویٰ کو ردّ کرنا تھا اس وجہ سے اس کو دس سورتیں بنانے کو کہا کہ تم کو ایک مثال نہیں دس مثالیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں.پس یہاں دس کا لفظ اس لئے نہیں رکھا گیا کہ وہ ایک سورۃ تیار کرسکتے تھے بلکہ اس لئے کہ ان کے اس اعتراض کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ انہیں کئی مواقع اعتراض کے دیئے جاتے اور سب اس لئے نہیں کہا کہ اس وقت جن معترضوں کا ذکر تھا وہ صرف بعض حصوں کو قابل اعتراض قرار دیتے تھے سب کو نہیں.سورۃ بنی اسرائیل کے مطالبہ اور سورۃ ہود کے مطالبہ کے فرق کی وجہ غرض سورۂ بنی اسرائیل میں چونکہ تکمیل کا دعویٰ تھا اس میں قرآن شریف کی مثل کا مطالبہ کیا گیا اور سورۂ ہود میں چونکہ کفار کے اس اعتراض کا جواب تھا کہ بعض حصے غیرمعقول ہیں اس لئے فرمایا کہ دس ایسے حصے جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور اور قابل اعتراض ہوں تم انہیں کے مقابل میں کوئی کلام بناکر پیش کردو.تاکہ کفار یہ نہ کہیں کہ ہمیں صرف ایک اعتراض کا حق دیا تھا اور اس کا مقابلہ کرنے میں ہم سے غلطی ہو گئی.سورئہ یونس والی تحدی اور ایک سورۃ کی مثل کا مطالبہ تیسرا مقام جس میں قرآن کریم کی بے مثلی کا دعویٰ ہے سورۂ یونس ہے اس میں ایک سورۃ کا مطالبہ کیا ہے جو پہلے دونوں مطالبوں سے کم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ اپنے ایک دعویٰ کے ثبوت کے لئے تھا نہ کہ کفار کے اعتراض کی تردید میں.اس جگہ اس آیت سے پہلے دعویٰ
Page 232
کیا گیا تھا کہ سب تصرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس کے ثبوت میں قرآن کریم کو پیش کرکے اس کے متعلق پانچ دعوے کئے تھے.وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ(یونس:۳۸).یعنی اول اس میں ایسی تعلیم ہے جسے انسان بنا ہی نہیں سکتا.دوم پہلی کتب کی اس میں تصدیق ہے.سوم اس میں پہلی کتب کے نامکمل احکام کو مکمل کیا گیا ہے.چہارم یہ کلام بالکل محفوظ اور انسانی دستبرد سے پاک ہے.پنجم اس کی تعلیم تمام قسم کے انسانوں اور تمام زمانوں کے لئے ہے.اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ سچ نہیں تو پھر تم بھی ایک سورۃ ایسی بناکر پیش کردو جس میں وہ پانچ باتیں جو بیان کی گئی ہیں ایسے مکمل طور پر بیان ہوں جیسی کہ اس سورۃ یعنی یونس میں بیان کی گئی ہیں.لیکن اگر ایک سورۃ کے مقابلہ میں بھی تم کوئی کلام نہ پیش کرسکو تو پھر سمجھ لو کہ سارے کلام میں کس قدر کمالات مخفی ہوں گے اور ان کا بنانا انسانی طاقت سے کس قدر بالا ہوگا.غرض کہ اس جگہ مِثْلِہٖ سے مراد ان پانچ کمالات کی مثل والا کلام ہے جو سورۂ یونس میں بیان کئے گئے ہیں.سورئہ طور والی تحدی کے بالمقابل کسی اور پیشگوئی کا مطالبہ اب رہی آخری آیت یعنی فَلْیَاْتُوْابِحَدِیْثٍ مِثْلَہٗ اِنْ کَانُوْا صٰدِقِیْنَ (الطور:۳۵) کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ایسی ہی بات پیش کرکے دکھاؤ.میرے نزدیک اس آیت میں سب سے چھوٹا مطالبہ ہے اور وہ صرف ایک مثال کا ہے.خواہ وہ ایک سورۃ سے بھی چھوٹی ہو اور یہ مطالبہ بھی اپنے دعوے کے ثبوت میں ہے نہ کہ کفار کے دعوے کے رد میں.اور وہ دعویٰ وہی ہے جو اس سورۃ کے شروع میں کیا گیا ہے.یعنی وَ الطُّوْرِ.وَ كِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ.فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ.وَّ الْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ.وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ.وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ.اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ.مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ(الطور:۲ تا ۹).یعنی یہ کتاب جس کا وعدہ طور پر دیا گیا تھا اور جو لکھی جائے گی اور ہمیشہ پڑھی جائے گی اور دنیا میں پھیلائی جائے گی اور اسلام جس کے متبعین کی تعداد بہت بڑھ جائے گی اور نہ صرف عوام بلکہ اعلیٰ طبقہ کے لوگ روحانی و جسمانی فضائل والے اس میں داخل ہوں گے.اور یہ روحانیت کا چشمہ جو مختلف ملکوں کو سیراب کرے گا ان دونوں امور کو ہم بطور قیامت کی دلیل کے پیش کرتے ہیں.اس ذکر کے بعد فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس کلام کو بناوٹی کہتے ہیں.اگر ایسا ہے تو جو جو اور جس جس قسم کی پیشگوئیاں اوپر پیش کی گئی ہیں ان کی مانند یہ بھی ایک پیشگوئی پیش کردیں.اور مفتریات کی بھی ہم شرط نہیں لگاتے.انہیں اجازت ہے کہ یہ چاہیں تو پچھلی الہامی کتب سے ہی کوئی ایسی مثال نکال کر پیش کردیں مگر یاد رکھیں کہ یہ اس کی نظیر کہیں سے نہیں لا سکتے.اس مطالبہ میں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بھی کوئی شرط نہیں اور نہ یہ شرط ہے کہ اپنے پاس سے کوئی پیشگوئی کریں.بلکہ اجازت دی ہے کہ خواہ خود بنالیں یا پچھلی کتب سے جو خواہ الہامی ہوں خواہ غیرالہامی
Page 233
نکال کر پیش کردیں اور پھر مطالبہ بھی نہایت چھوٹا رکھا ہے.کہ ایسی ایک ہی پیشگوئی پیش کردیں.حالانکہ قرآن کریم میں اور بھی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں اور پھر دشمن کے عاجز رہنے کی وجہ بھی بتادی ہے کہ ایسی پیشگوئی کے بیان کرنے کے لئے تو زمین اور آسمان کے خالق اور خزانوں کے مالک اور نگراں اور روحانی ترقی کے مالک اور غیب کے مالک کی ضرورت ہے اور یہ باتیں ان میں نہیں.پس یہ کیونکر اس کی مثل بناسکتے ہیں؟ دوسرے حصہ کو یعنی پہلی کتب سے مثال نہ لاسکنے کے دعویٰ کو رد کرنا ضروری نہیں سمجھا.کیونکہ وہ کتب سچی تھیں.صرف درجہ کا سوال تھا.یہ مطالبہ بھی باقی مطالبوں کی طرح اب تک قائم ہے.پھر کیا کوئی انسان خواہ کسی مذہب کا ہو سورۂ طور کی اس آیۃ کی مثل لانے کا دعویٰ کرسکتا ہے؟ اگر ہے تو آگے آکر اسے پیش کرے.سورئہ بقرہ والی تحدّی پانچواں مطالبہ سورۂ بقرہ میں ہے اور اس میں بھی سورۂ یونس کی طرح ایک سورۃ لانے کا مطالبہ ہے.چنانچہ فرماتا ہے وَ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ١۪ وَ ادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ(البقرۃ:۲۴).اس جگہ بھی اپنے دعویٰ کی ہی مثل طلب کی ہے اور وہ دعویٰ یہ ہے ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ١ۛۖۚ فِيْهِ١ۛۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۠ (البقرۃ:۳).سورۂ یونس کی آیت کے پہلے بھی لَارَیْبَ فِیْہِ ہے.گویا ایک سورۃ کی مثل کے مطالبہ کا لَارَیْبَ فِیْہِ سے خاص جوڑ ہے.اس مطالبہ سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ۠ ہے.یعنی اعلیٰ مدارج روحانیہ تک پہنچاتا ہے.پس فرمایا کہ اگر قرآن کریم کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس کے روحانی اثر کا مقابلہ کرلو.کوئی ایک ہی سورۃ لے آؤ جو قرآن کریم کے مقابلہ میں روحانی تاثیرات رکھتی ہو.قرآن کریم کی ہر ایک سورۃ اعلیٰ سے اعلیٰ تاثیرات پیدا کرنے والی ہے قرآن کریم میں یہ تاثیر ہے کہ اس کی کوئی سورۃ بھی آدمی پڑھے اس کے دل میں اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی تاثیرات پیدا ہونے لگیں گی.گویا بجائے شکوک پیدا کرنے کے وہ شکوک کو قطع کردیتا ہے.اور لوگوں کو ایسے مقامات تک پہنچادیتا ہے کہ وہاں شک باقی ہی نہیں رہتا اور یہ تعلق باللہ کا مقام ہے.یہ مقام صرف قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے.دوسرا کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور قرآن کریم کی ہر اک سورت ان روحانی تاثیرات میں ایسی بے مثل ہے کہ کوئی اور کلام اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا.اوپر کی تشریحات سے یہ امر ثابت ہے کہ درحقیقت یہ پانچوں مطالبے الگ الگ ہیں اور سب ایک ہی وقت میں قائم ہیں.کوئی مطالبہ کسی دوسرے مطالبہ کو منسوخ نہیں کرتا.اور سب غلطی اس امر سے لگی ہے کہ خیال کرلیا گیا
Page 234
ہے کہ جہاں جہاں مثل طلب کی گئی ہے وہاں صرف فصیح عربی کی مثل طلب کی گئی ہے.اور سب آیتوں میں ایک ہی مطالبہ ہے.حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے.ان پانچ سورتوں میں ایک ہی مطالبہ نہیں بلکہ مختلف مطالبے ہیں اور ہر مطالبہ کے مناسب حال پورے قرآن یا بعض قرآن کی مثل طلب کی گئی ہے.فصاحت و بلاغت میں نظیر کا مطالبہ اب رہا یہ سوال کہ آیا ان مطالبات میں فصاحت وبلاغت کا مطالبہ شامل ہے یا نہیں؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً شامل ہے.لیکن ضمنی طور پر.نہ کہ اصل مقصود کے طور پر.کیونکہ اعلیٰ مطالب بغیر اعلیٰ الفاظ اور عمدہ تراکیب کے ادا ہی نہیں ہوسکتے.پس چونکہ قرآن کریم بہترین مطالب پر حاوی ہے اس لئے ضروری تھا کہ اس کے لئے بہترین الفاظ اور بہترین طریقہ ادائیگی کو اختیار کیا جاتا.ورنہ اس کے مطالب مشتبہ رہتے اور جب قرآن کریم کا فصیح ترین الفاظ اور بلیغ ترین عبارات میں نازل ہونا اس کے مطالب کے لحاظ سے ضروری تھا اور وہ اسی رنگ میں نازل ہوا ہے تو جس جس حصہ کی مثل کا مطالبہ کیا گیا ہے اس میں فصاحت و بلاغت کا مقابلہ بھی ضرور شامل رہے گا.فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ پس اگر وہ تمہاری (یہ) بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ (یہ علوم کا خزانہ) جو( تم پر) اتارا گیا ہے اللہ (تعالیٰ) کے وَ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ١ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۰۰۱۵ (خاص) علم پر مشتمل ہے.اور یہ کہ اس کے سوا کوئی (ہستی) بھی پرستش کے لائق نہیں.پس کیا تم کامل فرمانبردار بنو گے( یا نہیں).تفسیر.قرآن کا علم الٰہی پر مشتمل ہونا اس کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ہے فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس چیلنج کو قبول نہ کریں تو اس سے ثابت ہوجائے گا کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کے علم پر مشتمل ہے.اور اس میں ایسے امور بیان ہوئے ہیں جنہیں انسان دریافت نہیں کرسکتا.تبھی تو ہر انسان اس کی مثل لانے سے قاصر ہے.دوسرے اس سے یہ بھی ثابت ہوجائے گا کہ خدا ایک ہی ہے.کیونکہ اگرایک سے زائد خدا ہوں تو جب انہیں بھی قرآن کریم کی مثل پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا ہے تو کیوں نہ وہ ایک ایسا ہی کلام پیش کرکے اسے جھوٹا ثابت کریں.سب طرف سے خاموشی کا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں
Page 235
یہ چیلنج ہمیشہ کے لئے ہے اس جگہ ایک سوال پیدا ہوسکتا تھا کہ یہ چیلنج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کے لئے ہی تھا یا اب بھی قائم ہے.اس سوال کا جواب جمع مخاطب کی ضمیر استعمال کرکے دے دیا گیا ہے کہ یہ چیلنج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لئے خاص نہیں بلکہ ہر زمانہ کے لئے کھلا ہے.اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خاص ہوتا تو اس کی جگہ یہ فرماتا کہ اگر وہ تیرے چیلنج کا جواب نہ دیں.لیکن فرمایا یہ ہے کہ اگر ’’تمہارے‘‘ چیلنج کا جواب نہ دیں.غرض لفظ ’’تمہارے‘‘ کے استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانہ میں مسلمانوں کو اس چیلنج کے پیش کرنے کا اختیار ہے.اور قرآن کریم ان خوبیوں میں ہمیشہ بے مثل رہے گا.فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ کے مخاطب کون ہیں؟ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ کا میرے نزدیک خطاب کفار سے ہے اور انہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے اور اس کے معارضہ سے ہر ایک غیراللہ کے عاجز ثابت ہونے کے بعد بھی کیا تم اسلام نہ لاؤگے.مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ جو (لوگ اس) ورلی زندگی (کے سامان) اور اس کی زینت کو( اپنا) مقصود بنائیں گے انہیں ہم ان کے اعمال اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَ هُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ۰۰۱۶ (کے پھل) اسی( زندگی) میں پورے پورے دے دیں گے اور انہیں اس میں کم نہیں دیا جائے گا.حلّ لُغَات.وَفّٰی فُلَانًا حَقَّہٗ تَوْفِیَۃً اَعْطَاہُ اِیَّاہُ وَافِیًا (اَیْ کَثِیْرًا) تَامًّا (اقرب) وَفّٰی کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اس کا حق پورا اور کثرت کے ساتھ ادا کر دیا.بَـخَسَہٗ یَبْخَسُ بَخْسًا.نَقَصَہٗ کم کر دیا وَمِنْہُ لَاتَبْخَسْ اَخَاکَ حَقَّہٗ اور اس سے یہ محاورہ ماخوذ ہے کہ اپنے بھائی کا حق کم نہ کر.اَوْعَابَہٗ یا اس کے معنی عیب لگانے کے ہوتے ہیں.وَبَخَسَ النَّاسَ أَخَذَمِنْہُمْ شَیْئًا بِاسْمِ الْعُشْرِ اور اس کے معنی عشر یعنی ٹیکس کے وصول کرنے کے بھی ہوتے ہیں.تفسیر.دنیا کا حصول دین پر موقوف نہیں فرماتا ہے جو کوئی ورلی زندگی کو اس کی زینت یعنی اموال و دولت کو چاہتا ہے ہم اس کو پورا پورا حق دے دیں گے.یعنی جس امر کے پیچھے وہ پڑا ہے اس سے محروم نہیں کیا جائے گا.جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ مسیحیوں کے پاس اس وقت بڑی دولت ہے انہیں اس آیت پر غور کرنا
Page 236
چاہیے.خدا تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا ملنا دین کے حصول پر منحصر نہیں.دین سے بیگانہ ہوکر بھی انسان دنیا حاصل کرسکتا ہے.کیونکہ حصول دنیا کے لئے بعض اور قواعد بھی ہیں.یعنی اس کے حصول کے لئے اصول طبعیات کے مطابق کوشش کرنا.پس دنیا کا ملنا بغیر دوسرے نشانات کی شمولیت کے خدا رسیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے.ہاں !یہ شرط لگائی گئی ہے کہ خالص دنیوی اعمال کا بدلہ ہر انسان کو اس دنیا میں ملتا ہے لیکن جن اعمال میں دین کو شامل کرلیا گیا ہو مگر خدا تعالیٰ کی منشاء کے مطابق وہ عمل نہ ہوں ان کا بدلہ نہیں ملتا.اَعْمَالَهُمْ فِيْهَاسے اسی طرف اشارہ ہے.دنیا میں انہماک کی سزا بصورت عذاب دنیا میں نہیں دی جائے گی لَا يُبْخَسُوْنَ یعنی دنیاوی اعمال میں ان پر کوئی عیب نہ لگایا جائے گا.یا یہ کہ اگر وہ ظلم نہ کریں گے تو اس دنیا میں ان پر کوئی عذاب نہ آئے گا.خواہ وہ دین کی طرف توجہ نہ کریں.عذاب دینی امور میں اسی وقت آتا ہے جب استہزاء اور شرارت کو استعمال کیا جائے.خالی انکار پر اس دنیا میں عذاب نہیں آتا.کیونکہ اصل دارالجزاء دوسرا جہان ہے.اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ١ۖٞ وَ یہ وہ( لوگ) ہیں جن کے لئے آخرۃ میں (دوزخ کی) آگ کے سوا (اور) کچھ نہیں ہو گا اور جو کچھ انہوں نے اس حَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَ بٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰۰۱۷ (ورلی زندگی) کی خاطر کیا ہوگا وہ( آخرت کے حق میں بالکل) بے سود ہو جائے گا اور جو کچھ وہ کرتے رہے ہوں گے وہ اکارت ہو جائے گا.حلّ لُغَات.حَبِطَ حَبِطَ الْعَمَلُ حُبُوْطًا وَحَبْطًا فَسَدَوَھَدَرَ.بے فائدہ اور بے ثمرہ ہو گیا اکارت ہو گیا.مَاءُ الْبِئْرِ ذَھَبَ ذَھَابًا لَایَعُوْدُ کَمَاکَانَ.کوئیں کا پانی ہمیشہ کے لئے منقطع ہو گیا جاتا رہا.(اقرب) بَطَل بَطَلَ فَسَدَ اَوْسَقَطَ حُکْمُہٗ خراب ہو گیا.اکارت ہو گیا.کالعدم ہو گیا.(اقرب) تفسیر.یہ آیت فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ کے جواب میں ہے کہ تم جو دین کی طرف رغبت نہیں کرتے اگر تم مسلمان نہ ہوگے تو دنیا کے سامان تو تمہیں مل جائیں گے لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی ترقی نہ ملے گی.مَا صَنَعُوْا فِيْهَا کی ضمیر مجرور کا مرجع مَا صَنَعُوْا فِيْهَا میں ضمیر مؤنث الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا کی طرف بھی پھیری جاسکتی ہے.اور آخرۃ کی طرف بھی.پہلی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ دنیا میں جو دنیا کی خاطر کام کئے ہوں گے
Page 237
چونکہ ان کا بدلہ مل چکا ہوگا.اس لئے اب وہ کام نہ آسکیں گے اور دوسری صورت میں یعنی آخرت کی طرف ضمیر پھیرنے کی صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ دنیا کے کام چونکہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے ماتحت تھے ان کا بدلہ تو مل گیا مگر اخروی کام چونکہ مقررہ قوانین کے خلاف تھے بوجہ ناقص ہونے کے فائدہ نہیں دیں گے.اور جس مقصد کے لئے تھے وہ حاصل نہ ہوگا.اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ وَ يَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَ پس کیا جو (شخص) اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر (قائم) ہے اور (اس کی صداقت کا) ایک گواہ اس مِنْ قَبْلِهٖ كِتٰبُ مُوْسٰۤى اِمَامًا وَّ رَحْمَةً١ؕ اُولٰٓىِٕكَ (یعنی خداوند تعالیٰ)کی طرف سے (آکر) اس کی پیروی کرے گا اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو (لوگوں يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ١ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ کے لئے) امام اور رحمت تھی( ایک جھوٹے مدعی جیسا ہو سکتا ہے ؟) وہ( یعنی موسیٰ کے سچے پیرو )اس پر (بھی ضرور) مَوْعِدُهٗ١ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ١ۗ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ایمان لاتے ہیں اور ان( مخالف) گروہوں میںسے جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو (دوزخ کی) آگ اس کے وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ۰۰۱۸ (لئے) وعدہ کی جگہ ہے.پس (اے مخاطب) تو اس کےمتعلق کسی( قسم کے) شک میں نہ پڑ.وہ یقیناً بالکل حق ہے(اور) تیرے رب کی طرف سے (ہے) لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لایا کرتے.حلّ لُغَات.اِمَامٌ اَلْاِمَامُ مَنْ یُؤْتَمُّ بِہٖ جس کی اقتداء کی جائے.لِلْمُذَکَّرِ وَالْمُؤْنَّثِ یہ لفظ مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے آتا ہے.وَمِنْہُ قَامَتِ الْاِمَامُ وَسَطَھُنَّ کہتے ہیں (عورتوں کی) امام نماز میں ان کے درمیان کھڑی ہوئی.مَاأُمْتُثِلَ عَلَیْہِ الْمَثَالُ.جس چیز کو کسی کام کے کرنے میں نمونہ ٹھہراکر اس کے مطابق کام کیا جائے.اس لفظ کے اور معنی بھی ہیں جو یہاں چسپاں نہیں ہوتے.مگر معنوں کے سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں اور
Page 238
وہ یہ ہیں اَلْخَیْطُ یُمَدُّ عَلی البِنَاءِ فَیُبْنٰی.یعنی وہ تاگہ جس کے ساتھ معمار دیوار کی کجی کومعلوم کرتے ہیں.(اقرب) رَحْمَۃٌ.اَلرَّحْمَۃُ رِقَّۃُ الْقَلْبِ وَاِنْعِطَافٌ یَقْتَضِی التَّفَضُّلَ وَالْاِحْسَانَ وَالْمَغْفِرَۃَ.یعنی رحمت دل کی نرمی اور ایسے جذبۂ ترحم کو کہتے ہیں جو فضل احسان اور بخشش کرنے کی تحریک کرے.(اقرب) حِزْبٌ.اَلْاَحْزَابُ حِزْبٌ کی جمع ہے.اَلْحِزْبُ اَلطَّائِفَۃُ جتھا.جَمَاعَۃُ النَّاسِ.لوگوں کا گروہ.جُنْدُ الرَّجُلِ وَاَصْـحَابُہُ الَّذِیْنَ عَلٰی رَأْیِہٖ.کسی آدمی کے ساتھی اور وہ لوگ جو اس کے خیال کے مطابق ہوں.وَمِنْہُ فِی الْقُرْاٰنِ اُوْلٰٓئِکَ حِزبُ الشَّیْطَانِ اور انہی معنوں میں قرآن کریم میں حِزْبُ الشَّیْطَانِ کے الفاظ آئے ہیں.وَکُلُّ قَوْمٍ تَشَاکَلَتْ قُلُوْبُہُمْ وَاَعْمَالُھُمْ فَہُمْ اَحْزَابٌ وَاِنْ لَّمْ یَلْقَ بَعْضُہُمْ بَعْضًا.اور تمام وہ لوگ جن کے دلی خیالات اور اعمال ہم رنگ ہوں.احزاب کہلاتے ہیں خواہ ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا بھی نہ ہو.(اقرب) مِرْیَۃٌ.اَلْمِرْیَۃُ اِسْتِخْرَاجُ مَاعِنْدَ الْفَرَسِ مِنَ الْجَرْیِ گھوڑے کو جس قدر اس کی طاقت تھی دوڑایا.اَلْمِرْیَۃُ وَالْمُرْیَۃُ اَلشَّکُّ شک.وَیَقُوْلُوْنَ مَافِیْہِ مِرْیَۃٌ اَیْ جَدَلٌ کہتے ہیں کہ ا س میں مریہ نہیں ہے یعنی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے.(اقرب) تفسیر.قرآن شریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پرکھنے کے لئے تین گر بتائے گئے ہیں.اور فرمایا ہے کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں وہ جھوٹا نہیں ہوسکتا.اَفَمَنْ كَانَ کا جواب کَمَنْ ھُوَکَاذِبٌ محذوف ہے.یعنی کیا اوپر کی صفات والا شخص جھوٹوں کے زمرہ میں شامل ہوسکتا ہے؟ یا یہ کہ جو ایسا ہوکیا وہ اپنے مخالف کی طرح ہوسکتا ہے.اور اس صورت میں یوں عبارت ہوگی.أَفَمَنْ کَانَ عَلٰی بَیِّنَۃٍ کَمَنْ لَّیْسَ عَلٰی بَیِّنَۃٍ.یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ عام طور پر ایسے فقروں میں جواب کے حصے کو حذف کر دیا کرتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر تین قسم کے گواہ دنیا میں اس سچائی سے تعلق رکھنے والے تین قسم کے لوگ ہوسکتے ہیں.(۱) ایک وہ جو اس وقت اس کے مخاطب ہوں.(۲) وہ جو اس وقت تو مخاطب نہ ہوں لیکن آئندہ مخاطب بننے والے ہوں.(۳) تیسرے وہ لوگ جو پچھلے زمانہ میں گذر چکے ہوں.لیکن وہ اس آنے والے تغیر کی امید رکھتے تھے اگر ان تینوں قسم کے گواہوں سے کسی امر کی سچائی ثابت ہو تو اس سچائی میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہوسکتا.کیونکہ تینوں کے تینوںز مانے اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں.جو لوگ کسی صداقت کے منتظر ہوں لیکن ابھی وہ صداقت ظاہر نہ ہوئی ہو ان کے ایمان کی بنیاد خالص طور پر امور غیبیہ پر ہوتی ہے.اور جن لوگوں کے
Page 239
سامنے وہ صداقت آگئی ہو وہ اس کو دو پہلوؤں سے دیکھتے ہیں.(۱) کیا اس کی ذات میں کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جس سے اس کا سچائی ہونا ثابت ہوتا ہو؟ (۲) اس سچائی کے متعلق جو پہلی کتب میں خبریں تھیں کیا وہ اس کے ذریعہ سے پوری ہوجاتی ہیں؟ جب یہ زمانہ بھی گزر جاتا ہے اور ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جن کے لئے یہ سب باتیں قصہ ہوجاتی ہیں تو ان کے لئے ایک تیسری شہادت پیدا کی جاتی ہے اور وہ اس صداقت کے ثمرات ہیں.وہ لوگ علاوہ پہلی دونوں قسم کی دلائل کے اس امر پر بھی غور کرسکتے ہیں کہ اس صداقت کے ثمرات کیا پیدا ہوئے ؟اور اگر اس کے ثمرات ان کے زمانہ تک پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ صداقت ان کے زمانہ سے بھی ویسا ہی تعلق رکھتی ہے جیسا کہ پہلے زمانوں سے.ان شہادتوں کی ترتیب درجہ کے لحاظ سے اندرونی شہادت سب سے اہم ہوتی ہے کیونکہ وہ زمانۂ حال اور آئندہ دونوں زمانوں کے لوگوں کے لئے گواہ ہوتی ہے.اور نیز اس لئے کہ وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی زحمت سے آزاد کردیتی ہے اور خود اپنی ذات میں ہی صداقت کو ثابت کر دیتی ہے.دوسرے نمبر پر اس دلیل کو اہمیت حاصل ہوتی ہے جو صداقت کے ثمرہ کے طور پر آتی ہے.اس لئے کہ وہ بھی بعد میں آنے والے مخاطبین کے لئے ضروری ہے اگر وہ نہ ہو تو بعد میں آنے والوں کے لئے صداقت مشتبہ رہے.کیونکہ کسی چیز کا خالی صداقت ثابت ہونا اس پر عمل کرنے کے لئے کافی محرک نہیں ہوتا.بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ بھی ثابت کیا جائے کہ وہ صداقت موجودہ زمانہ میں بھی قابل عمل ہے.اور یہ بات نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور صداقت ظاہر ہوکر اسے منسوخ کرچکی ہے.اور جب کسی صداقت کے تازہ ثمرات ظاہر ہوتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ وہ صداقت موجودہ زمانہ کے لئے بھی ویسی ہی مفید ہے جیسے کہ گزشتہ زمانہ کے لوگوں کے لئے تھی.تیسرے نمبر پر اہمیت ان گزشتہ پیشگوئیوں کو حاصل ہوتی ہے جو لوگوں کو کسی صداقت کی امید دلاتی چلی آئی ہوں.یہ دلیل بھی اپنی ذات میں کارآمد ہوتی ہے کیونکہ ایمان کے لئے لوگوں کے دلوں کو تیار رکھتی ہے.گو اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے زمانہ میں وہ صداقت ظاہر ہو جس کی خبر پیشگوئیوں میں دی گئی ہو.قرآن کریم کی تائید میں ان تینوں قسم کے دلائل کو پیش کیا گیا ہے.وہ اپنی ذات میں بھی صداقت کے ثبوت رکھتا ہے.اس سے پہلے کی کتب میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے اور بعد میں بھی اس کے ثمرات ایسے طور پر ظاہر ہوتے رہیں گے کہ لوگوں کو اس کے انکار کی گنجائش نہ ہوسکے گی.چنانچہ سب سے پہلے فرماتا ہے کہ قرآن کریم یا اس کا لانے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے ساتھ ایسے دلائل رکھتا ہے جو قطعی طور پر ثابت کرتے
Page 240
ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور چونکہ قرآن کریم کا زمانہ ممتد ہونے والا تھا اور اس نے بعید ترین زمانہ کے لوگوں کو بھی ہدایت دینی تھی اس لئے فرمایا کہ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ.اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے جب اتنا عرصہ گذر جائے گا کہ پہلے دلائل قصوں کے رنگ میں رہ جائیں گے تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نیاگواہ آجائے گا.پھر فرمایا کہ علاوہ ان موجودہ دلائل کے گذشتہ نبیوں نے بھی اس کی خبر دی ہوئی ہے.جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے کہ وہ امام ہے یعنی لوگوں کو کھینچ کھینچ کر ادھر لاتی ہے اور رحمت ہے کہ قرآن کے ماننے کے لئے اس نے لوگوں کے واسطے آسانیاں کردی ہیں اُولٰٓىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ یعنی جن لوگوں کے لئے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت بن جاتی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں.آنحضرت صلعم کے بعد فَتْرَۃ یہاں اس سوال کا جواب بھی آجاتا ہے جو کہتے ہیں کہ گزشتہ تیرہ سو سال میں کیوں کوئی مامور نہیں آیا کیونکہ آنے والے کے لئے شاہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.اور ظاہر ہے کہ شاہد کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے کہ جب کسی صداقت کے متعلق یہ خیال ہو کہ اب بھی یہ ماننے کے قابل ہے یا نہیں.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی وقت کسی مامور کی ضرورت ہوسکتی تھی جب قرآن کریم کے متعلق یہ سوال پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ ماننے کے قابل ہے یا نہیں اور اس کی صداقت قابل عمل ہے یا نہیں؟ اور پچھلے تیرہ سو سال میں کبھی بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا.ہاں آج قرآن کے متعلق یہ سوال کئی گروہوں کی طرف سے پیدا ہورہا ہے.پہلی شہادت (اوّل) خود مسلمانوں کے نزدیک اس کی بعض تعلیمیں اب قابل عمل نہیں رہیں.ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے.جیسے نماز ور وزہ کے احکام، چور کے ہاتھ کاٹنے، پردہ اور سود وغیرہ احکام کے متعلق لوگوں میں سوالات پیدا ہورہے ہیں.دوسری شہادت (دوسرے) بہاء اللہ اور باب جیسے مدعیوں کے ماننے والوں کی طرف سے جو قرآن کریم کی شریعت کو منسوخ قرار دے کر نئی شریعت جاری کرنے کا اعلان کرتے ہیں.تیسری شہادت (تیسرے) یہ سوال اٹھایا جارہا ہے ان علوم جدیدہ کے محققین کی طرف سے جو تاریخی و عملی رنگ میں قرآن کریم پر حملہ آور ہیں.یہ حالات اس زمانے سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے.اس لئے اس زمانہ سے پہلے کسی شاہد کی بھی ضرورت نہ تھی.شَاهِدٌ مِّنْهُ کے معنی شَاهِدٌ مِّنْهُ کے متعلق مفسرین نے اختلاف کیا ہے.بعضوں نے شاہد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوراَفَمَنْ كَانَ سے مومن مراد لئے ہیں.مگر یہ معنی بالکل خلاف عقل ہیں.کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
Page 241
پہلے تھے اور مومن پیچھے تھے اور اس آیت میں اَفَمَنْ كَانَ والا وجود پہلے اوريَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ والا پیچھے بتایا گیا ہے.بعض نے شَاهِدٌ مِّنْهُ کے معنی ابوبکر کے اور بعض نے حضرت علی کے کئے ہیں مگر یہ بھی درست نہیں کیونکہ آیت میںشَاهِدٌ کے لئے مِنْہُ کی شرط لگائی گئی ہے.یعنی وہ شاہد خدا تعالیٰ کی طرف سے اس شہادت کے لئے حکم پاکر کھڑا ہوگا.اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی کی طرف سے ہرگز یہ دعویٰ نہ تھا کہ ان کو خدا تعالیٰ نے شہادت کے لئے مبعوث کیا ہے.بعض لوگوں نے عبداللہ بن سلام کو شاہد قرار دیا ہے.لیکن ان پر بھی یہی اعتراض پڑتا ہے.پس جاننا چاہیےکہ اس جگہ خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہی ذکر ہے جن کا نزول خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی رنگ میں ہونا تھا جیسے کہ پہلے بَیِّنَہ کا نزول ہوا تھا.اور جن کی آمد کی غرض یہ تھی کہ وہ اسلام کی صداقت کی شہادت تازہ نشانوں سے دیں جبکہ اسلام کی صداقت اور اس کی قوت قدسیہ کے خلاف بہت سے امور جمع ہونے والے تھے.کتاب موسیٰ کی شہادت کتاب موسیٰ کی شہادتیں بہت سی ہیں لیکن بڑی موٹی شہادت وہ ہے جو استثناء باب ۱۸ آیت ۱۸ میں ہے.موسیٰ علیہ السلام کی کتاب قرآن کریم کے لئے مندرجہ ذیل طریق پر امام و رحمت ہے.اوّل پیشگوئیوں کے ذریعہ سے.دوم منہاج نبوت کو واضح کرکے.سوم تعلیم کے مقابلہ کے لحاظ سے.چہارم اصول شرائع کے سمجھانے میں مدد دے کر.شَاهِدٌ مِّنْهُ میں بہائی ازم کا رد یہ بھی یاد رکھنا چاہیےکہ يَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ میں آئندہ زمانہ میں ایک گواہ کی امید دلائی گئی ہے.جو اس کی صداقت کو لوگوں سے منوائے گا.نہ کسی ایسے شخص کی جو قرآن کریم کی تعلیم کو منسوخ کرے گا.پس اس آیت میں بہائیوں کا رد ہے اور یہ ان پر حجت ہے کیونکہ گو وہ قرآن کریم کو سچا تسلیم کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ اب گزر گیا ہے اور بہاء اللہ کو قرآن کریم کا موعود وجود قرار دیتے ہیں.لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ موعود وجود قرآن کریم کو ہمیشہ کے لئے قابل عمل ثابت کرنے کے لئے اور اس کی صداقت کا گواہ بن کر آئے گا.نہ کہ اسے منسوخ کرنے کے لئے.پس ایسا کوئی شخص جو قرآن کریم کو منسوخ کرتا ہے قرآن کریم کا موعود نہیں ہوسکتا.فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ قرآن کریم کے مخاطبوں کے لئے ہے فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ سے مطلق مخاطب مراد ہیں نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم.کیونکہ اس سے پہلے کہا جاچکا ہے کہ اُولٰٓىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ یعنی ایک ایسی
Page 242
جماعت پیدا ہوچکی ہے جو قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے.پس یہ معنی نہایت ہی خلاف عقل ہوں گے کہ پچھلے بیان کردہ دلائل سے ایک جماعت تو مومنوں کی پیدا ہوچکی ہے لیکن جس پر وہ دلائل نازل ہوئے ہیں وہ ابھی شک میں ہی ہے.پس یقیناً اس کے معنی یہ ہیں کہ اے مخاطب! اس میں شک نہ کیجیئو.احزاب سے مراد مخالفین کی جماعتیں ہیں احزاب کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس سے عام طور پر مراد انبیاء کی مخالف جماعتیں ہوتی ہیں.چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لئے تشریف لائے تھے اس لئے اس جگہ پر ساری دنیا کے مذاہب اور ساری دنیا کی قومیں مراد لی جائیں گی.وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا١ؕ اُولٰٓىِٕكَ اوراس سے زیادہ کون ظالم (ہو سکتا) ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے.ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کئے يُعْرَضُوْنَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَ يَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰؤُلَآءِ الَّذِيْنَ جائیں گے اور تمام گواہ کہیں گے (کہ) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا سنو ! كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ١ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَۙ۰۰۱۹ ان ظالموں پر اللہ (تعالیٰ) کی لعنت ہے.تفسیر.جھوٹے اور سچے مدعیان نبوت میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا کیا لطیف بات فرمائی کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا سب سے زیادہ ظالم ہوتا ہے.اور جھوٹوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے.پس جھوٹے نبیوں اور سچوں میں فرق کرنا فی الحقیقت کچھ مشکل نہیں ہوتا.جھوٹے نبی اپنی شکل سے پہچانے جاتے ہیں.چنانچہ سچے انبیاء قیامت کے دن جھوٹے انبیاء کی طرف اشارہ کرکے کہیں گے کہ لوگو! دیکھو جھوٹے ایسے ہوتے ہیں تم لوگ اپنے خبث باطن کی وجہ سے ہمیں جھوٹا سمجھتے تھے.
Page 243
الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا١ؕ وَ جو اللہ (تعالیٰ کی طرف پہنچنے )کی راہ سے (لوگوں کو) روکتے ہیں.اوراس کی کجی چاہتے ہیں.اور یہی (لوگ) پیچھے هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ۰۰۲۰ آنے والی (گھڑی) کے( سب سے بڑے) منکر (ہوتے) ہیں.حلّ لُغَات.عِوَجٌ اَلْعِوَجُ اِسْمٌ لِضِدِّ الْاِسْتِقَامَۃِ ٹیڑھا ہونا.اَلْاِنْحِنَاءُ کجی.وَالْعِوَجُ یَکُوْنُ فِی الْمَعَانِی کَمَا یَکُوْنُ اَلْعَوَجُ فِی الْاَجْسَامِ جس طرح جسموں کے ٹیڑھا ہونے کے لئے عَوَجَ کا لفظ ہوتا ہے اسی طرح معانی و صفات کی کجی اور نادرستی کے لئے عِوَجٌ کا لفظ استعمال ہوتا ہے.(اقرب) تفسیر.يَبْغُوْنَهَا عِوَجًاکے معنی وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًاکے دو معنی ہیں.اول یہ کہ اس کے لئے کجی چاہتے ہیں.عربی میں کہتے ہیں بَغَیْتُکَ الشَرَّ أَیْ طَلَبْتُ لَکَ الشَّرَّ(فتح البیان زیر آیت ھٰذا ).مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کجی آجاوے.وہ بگڑ جائے.یعنی صرف لوگوں کو ہی نہیں روکتے بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی خوبی بھی لوگوں کی نگہ سے پوشیدہ ہو جائے اور ایسے طریق اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر سے کلام الٰہی کا حسن مخفی رہے.اور اس میں لوگوں کو عیوب نظر آنے لگیں.یہ ایک عام حربہ ہے جو حق کے دشمن چلایا کرتے ہیں.وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ حق کا حسن پوشیدہ ہوجائے.اور ایسے ایسے جھوٹے الزام تراشتے ہیں کہ جن کو سن کر ناواقف لوگ خوبی کو بھی عیب دیکھنے لگتے ہیں.دوسرے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ یَبْغُوْنَہَا میں لِاَھْلِ کو محذوف سمجھا جائے.اور مراد یہ ہو کہ جو لوگ اللہ کے راستہ پر چلنے والے ہیں ان کے لئے کجی چاہتے ہیں یعنی انہیں گمراہ کرنا یا تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں.یہ معنی بھی مذکورہ بالا محاورہ ہی کے ماتحت آتے ہیں.اُولٰٓىِٕكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَ مَا كَانَ لَهُمْ یہ (لوگ) ملک میں( الٰہی سلسلوں کو) عاجز کر دینے والے نہیں ہوتے اور نہ (ہی) اللہ (تعالیٰ) کو چھوڑ کر ان کے کوئی مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ١ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ١ؕ مَا (دوست و ) مددگارہوتے ہیں ان کو دوہرا عذاب دیا جاتا ہے (دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی) وہ (کچھ بھی)
Page 244
كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ۰۰۲۱ سن نہیں سکتے اور نہ وہ (کچھ) دیکھ سکتے ہیں.تفسیر.اَرْضٌ کے معنی کل زمین کے ہوتے ہیں لیکن جب کسی خاص قوم کا ذکر ہو تو اس وقت ان کی زمین یعنی ان کا ملک مراد ہوتا ہے.فرماتا ہے کہ افتراء کرنے والے کبھی بھی ملک میں غلبہ نہیں پاسکتے.یعنی ان کی تدابیر دوسروں پر غالب نہیں آسکتیں.جھوٹوںکو کبھی دوست اور مددگارنصیب نہیں ہو تے وہ خود ہی اپنی کوششوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو نصرت نہیں ملتی اور اس پر افتراء کرنے کی وجہ سے اور اس کے خلاف چلنے کے سبب سے وہ کہیں بھی مددگار نہیں پاتے.یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا.بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا دوست نہیں ہوتا جو ان کے کام آسکے اور ان کے مقصد کے بڑھانے میں ممد ہوسکے.مِنْ دُوْنِ اللّٰهِکے معنی اس آیت کا یہ بھی مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ تو ان کا دوست ہوتا ہے مگر دوسرے لوگ دوست نہیں ہوتے.بلکہ مراد یہ ہے کہ بوجہ افتراء کے خدا تعالیٰ تو ان کا دوست ہوہی نہیں سکتا.مگر اس کے غضب کی وجہ سے جو ان کے ہمرنگ دوست ہوتے ہیں وہ بھی ان کے کام نہیں آسکتے.يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ کے معنی ضعف کے معنی دگنے کے بھی اور زیادتی کے بھی ہوتے ہیں.پس اس کے دونوں معنی ہیں.ایک یہ کہ انہیں دگنا عذاب ہوگا.اپنے گناہوں کا بھی اور ان کا بھی جنہیں انہوں نے گمراہ کیا.دوسرے یہ کہ ان کا عذاب بڑھتا جائے گا.کیونکہ وہ ایک غلط تعلیم پھیلا کر دنیا میں بدی کا بیج پھیلا گئے ہیں.نفی سمع و بصر کے معنی مَا كَانُوْا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ السَّمْعَ وَ مَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ کا مطلب یہ ہے کہ تعجب ہے کہ جھوٹے مدعی نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں.حالانکہ ان سے پہلے دونوں قسم کے نبی گزر چکے ہوتے ہیں.سچے بھی اور جھوٹے بھی.لیکن نہ یہ ان کے انجام کو دیکھتے ہیں نہ ان کے حالات کو سنتے ہیں.
Page 245
اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا یہ وہ (لوگ ہیں) جو اپنے نفسوں کے متعلق گھاٹے میں رہیں گے اور جس (مدعا) کے لئے وہ (اللہ تعالیٰ پر) جھوٹ يَفْتَرُوْنَ۰۰۲۲ باندھتے تھےوہ ان (کے ہاتھ) سے جاتا رہے گا.حلّ لُغَات.خَسِرَ ضِدُّ رَبِـحَ نفع کے مقابل کا لفظ ہے یعنی گھاٹا کھایا.ضَلَّ گمراہ ہوا.ھَلَکَ ہلاک ہوا.(اقرب) خَسِرَ متعدی نہیں بلکہ لازم ہے عربی زبان میں یہ لفظ ہمیشہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے.میں نے بڑی تحقیق کی ہے مگر مجھے نہیں ملا کہ یہ لفظ عربی کے استعمال میں کہیں بھی متعدی استعمال ہوا ہو.مگر یہ عجیب بات ہے کہ تمام کے تمام مفسرین خسروا کے معنی اھلکوا کرتے ہیں لیکن تاج العروس والا کہتا ہے کہ سارے اہل تصریف اس کو لازم ہی قرار دیتے ہیں مگر وہ سب غلطی پر ہیں کیونکہ قرآن کریم میں متعدی استعمال ہوا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ لازم ہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہماری لغتیں مذہبی اثر کے نیچے ہیں اور تفسیروں کے ماتحت لغت کو بھی کر دیا گیا ہے جس سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا.بلکہ نقصان پہنچا ہے اور کئی معارف قرآنیہ اس تصرف کی وجہ سے لوگوں کی نظر سے مخفی ہو گئے ہیں.کاش کوئی شخص ہمت کرکے ایسی لغت تیار کرے جو تفسیروں کے اثر سے بالکل آزاد ہو تاکہ لوگ اس ناجائز دباؤ سے بالکل آزاد ہوجائیں اور قرآن کریم کے سمجھنے میں لوگوں کو سہولت حاصل ہوجائے.خَسِرَ کے لفظ کے متعلق ہی اگر تفسیروں کا رعب ماننے کی بجائے عربی کے قواعد پر نظر کی جائے تو اسے خلاف محاورہ متعدی بنانے کی ضرورت نہ تھی.ہم اس کے معنی اس طرح کرسکتے ہیں جس طرح سَفِہَ نَفْسَہٗ کے معنی کرتے ہیں.یعنی صرف جارمحذوف تصور کرتے ہیں.اور جملہ کو یوں تصور کرتے ہیں کہ سَفِہَ فِی نَفْسِہٖ یا تمیز خیال کرتے ہیں.جو شاذ و نادر طور پر معرفہ بھی آجاتی ہے.اسی طرح ہم خَسِرُوْا اَنْفُسَہُمْ کے بھی یہ معنی کرسکتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے بارہ میں گھاٹے میں پڑ گئے اور یہ معنی دوسرے معنوں سے زیادہ زوردار بھی ہوجاتے ہیں.اور یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کا سب فریب خود اپنے ہی نفسوں کے خلاف پڑا ہے.تمیز کی صورت میں بھی زور قائم رہتا ہے اور معنی اوپر والے ہی رہتے ہیں.خَسِرَ الرَّجُلُ ضَلَّ وَھَلَکَ ہلاک ہوگیا.(اقرب)
Page 246
لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ۰۰۲۳ یہ اٹل (بات) ہے کہ آخرت میں وہی (سب سے) زیادہ گھاٹا پانے والے ہوں گے.حلّ لُغَات.لَاجَرَمَ جَرَمَ یَـجْرِمُ جَرْمًا.قَطَعَ کاٹ دیا.لَاجَرَمَ قَالَ الفَرَّاءُ ھِیَ کَلِمَۃٌ کَانَتْ فِی الْاَصْلِ بِمَنْزِلَۃِ لَابُدَّ وَلَا مَحَالَۃَ فَـجَرَتْ عَلَی ذٰلِکَ وَکَثُرَتْ حَتّٰی تَحَوَّلَتْ اِلٰی مَعْنَی الْقَسَمِ.وَصَارَتْ بِمَنْزِلَۃِ حَقًّا وَھُوَمَأْخُوْذٌ مِّنَ الْقَطْعِ.فراء کا قول ہے کہ لَاجَرَمَ پہلے لَابُدَّ یعنی ضرور کے معنی میں استعمال ہوا کرتا تھا پھر کثرت سے استعمال ہوتے ہوتے اس کے معنی قسم کے بن گئے اور حَقًّا یعنی یقیناً کے معنی دینے لگا ورنہ اس کے اصل معنی یہی ہیں کہ اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا یعنی یہ اٹل بات ہے.(اقرب) تفسیر.اُخروی نقصان صرف کفّار کو پہنچے گا یعنی دنیا میں تو یہ لوگ انبیاء کو اپنی شرارتوں سے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچالیتے ہیں خواہ وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو لیکن آخرت میں سب نقصان انہی کو پہنچے گا.اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَخْبَتُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ١ۙ جو (لوگ) ایمان لائے اور انہوں نے نیک (اور منا سب حال) عمل کئے اور اپنے رب کی طرف جھک گئے وہ یقیناً اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ١ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۰۰۲۴ بہشت (میں رہنے) والے ہیں وہ اس میں رہا کریں گے.حلّ لُغَات.اَخْبَتَ اَخْبَتَ اِلٰی اللہِ اِطْمَئَنَّ اِلَیْہِ وَتَخَشَّعَ اَمَامَہٗ.اللہ تعالیٰ کے سامنے فروتنی اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو گیا.وَاَصْلُہٗ اَخْبَتَ اَیْ صَارَ اِلَی الْخَبْتِ اَیْ الْاَرْضُ الْمُتِّسَعُ الْمُطْمَئِنُّ.اور اصل میں یہ اخبت سے نکلا ہے.جس کے معنی ایک وسیع اور نشیب والی زمین میں داخل ہوجانے کے ہیں.(اقرب) گویا اس لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے سامنے فروتنی کے ساتھ آکر اطمینان پاتے اور آرام محسوس کرتے ہیں اور سب اطراف سے منہ موڑ کر اس کی طرف جھک جاتے ہیں.اور جس طرح کھلی زمین میں چلنے پھرنے میں سہولت ہوتی ہے.اسی طرح وہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے میں اطمینان اور لذت پاتے ہیں.تفسیر.قرب الٰہی کی شرائط اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کمالات روحانیہ کے لئے ایمان اور
Page 247
اعمال صالحہ ہی کافی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ پر یقین اور تسلی اور اس سے محبت کی بھی ضرورت ہے.جس طرح بچہ ماں کے پاس جاکر تسلی پاتا ہے یہی حال اس شخص کا ہونا چاہیےجو روحانیت میں ترقی کرنا چاہتا ہے.اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو اور اس پر اعتماد کامل ہو اور اس کی طرف رجوع ہو.جب تک یہ بات حاصل نہ ہوگی کبھی بھی قرب الٰہی نصیب نہ ہوگا.مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَ الْاَصَمِّ وَ الْبَصِيْرِ وَ السَّمِيْعِ١ؕ ان دونوں گروہوں کی حالت ایک اندھے اور بہرے اور ایک بینا اور خوب سننےوالے کی( حالت کی) طرح ہے.هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا١ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَؒ۰۰۲۵ کیا ان (دونوں) کی حالت برابر ہو سکتی ہے (تو) کیا پھر (بھی) تم نہیں سمجھتے.حلّ لُغَات.فَرِیْقٌ اَلْفَرِیْقُ الطَّائِفَۃُ مِنَ النَّاسِ اَکْثَرُ مِنَ الْفِرْقَۃِ.لوگوں کا ایک گروہ.لیکن یہ لفظ فرقہ کی نسبت زیادہ کثرت افراد کو ظاہر کرتا ہے.وَرُبَّمَا اُطْلِقَ الفَرِیْقُ عَلَی الْجَمَاعَۃِ قَلَّتْ اَوْکَثُرَتْ.اور بعض دفعہ یہ لفظ مطلق جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے.خواہ وہ چھوٹی جماعت ہو یا بڑی.(اقرب) تفسیر.أَعْمٰی اور أَصَمّ کا لفظ اور کفر کی حقیقت اس آیت میں ایمان و کفر کا مقابلہ کیا ہے.مومن کو بینا قرار دیا ہے اور کافر کو اندھا.اور مومن کو سننے والا اور کافر کو بہرا.قرآن کریم گالی نہیں دیتا بلکہ حقائق بیان کرتا ہے.پس ہم یہ خیال نہیں کرسکتے کہ کافر کو یونہی اس نے اندھا اور بہرا کہہ دیا ہے.اس مثال میں یقیناً کفر کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور اس امر کو سمجھنے کے لئے ہمیں اندھے اور بہرے اور بینا اور سننے والے کے فرق کو معلوم کرنا چاہیے.پہلے ہم نابینا اور بینا کو لیتے ہیں.سو سب سے پہلا فرق ہمیں ان دونوں میں یہ نظر آتا ہے کہ بینا تو نور کو دیکھ سکتا ہے لیکن اندھا نہیں دیکھ سکتا.اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی محبت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کلام کو پہچان لیتے ہیں لیکن دوسرے نہیں پہچان سکتے.دوسرا فرق یہ ہے کہ اندھا فوراً اپنی مقصود چیز تک نہیں پہنچ سکتا.بلکہ ٹھوکریں کھاتا ہوا اور ٹٹولتا ہوا پہنچتا ہے.اس کے برخلاف بینا اپنی مقصود چیز تک فوراً پہنچ جاتا ہے.تیسرا فرق یہ ہے کہ مقابلہ کے وقت اندھا اپنے اور پرائے میں فرق نہیں کرسکتا.بالکل ممکن ہے کہ اپنے ساتھی ہی کو مار بیٹھے لیکن بینا یعنی آنکھوں والا دشمن کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے.یہی فرق سچے دین کے متبع اور اس کے منکر میں ہوتا ہے.سچے دین کا متبع خدا تعالیٰ کے منشاء کو جو روحانیت کے
Page 248
لئے بمنزلہ نور ہے کہ جس سے روحانی راستوں کا علم ہوتا ہے پہچان لیتا ہے لیکن جو شخص سچائی کا منکر ہے اس کی روحانی آنکھ ماری جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے پہچاننے سے محروم رہ جاتا ہے اسی طرح سچائی کو پانے والا چونکہ خدا تعالیٰ کے الہام کا طالب ہوتا ہے وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا.بلکہ فوراً اپنے منزل مقصود کو پالیتا ہے.اس کے برخلاف جو لوگ اپنی عقل سے کام لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی گو کبھی صداقت کو پالیتے ہیں لیکن ہزاروں ٹھوکریں کھانے کے بعد.اس کی ایک موٹی مثال حرمت شراب کی ہے.اسلام نے تو اسے فوراً حرام کر دیا اور مسلمان رک گئے.دوسری دنیا تیرہ سو سال دھکے کھانے کے بعداب اس کی برائیوں کی قائل ہونے لگی ہے.تیسرا فرق بھی ظاہر ہے سچائی کے ماننے والے ایک اصل پر قائم ہوتے ہیں اور ان کے عقائد میں اختلاف نہیں ہوتا.لیکن جھوٹ کے متبع نہیں جانتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بسا اوقات ایک سچائی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے ان سچائیوں پر بھی حملہ کرجاتے ہیں جن کو وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں.اسی وجہ سے قرآن کریم بار بار اپنے مخالفین کو توجہ دلاتا ہے کہ اسلام پر حملہ کرتے ہوئے تم اپنے مسلمات کو بھی بھول جاتے ہو.اور نہیں جانتے کہ جو حملہ تم اپنے خیال میں اسلام پر کرتے ہو وہ خود تمہارے معتقدات پر پڑتا ہے.بہرہ اور کا فر دوسری تشبیہ بہرے اور سننے والے کی دی ہے ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھالیتا ہے اور دوسرا اس سے محروم رہ جاتا ہے.کیونکہ نہ وہ سنتا ہے نہ اسے دوسروں کے خیالات پر آگاہی حاصل ہوتی ہے.یہی اسلام اور غیراسلام اور مسلم اور غیرمسلم میں فرق ہے.اسلام اور مسلمان تو ساری سچائیوں کو اپنے اندر جمع کرلیتے ہیں لیکن اس کے دشمن صرف اپنے پرانے خیالات پر قانع ہیں.وہ دوسری سچائیوں سے اپنےکانوں میں روئی ڈال کر غافل بیٹھے ہوئے ہیں.اسی فرق کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اشارہ فرمایا ہے کہ کَلِمَۃُ الْحِکْمَۃِ ضَآلَّۃُ الْمُوْمِنِ اَخَذَ ھَا حَیْثُ وَجَدَھَا (جامع ترمذی ابواب العلم باب ما جاء فی فضل الفقہ علی العبادۃ) حکمت کی بات تو مومن ہی کی گم شدہ چیز ہے وہ جہاں اسے پاتا ہے لے لیتا ہے.غرض جو سچا مذہب ہوتا ہے وہ تمام سچائیوں کو اپنے اندر جمع کرلیتا ہے.اور جھوٹا ضد اور تعصب کو اختیار کرتا ہے.ہر صداقت کو اپنی چیز سمجھنے کی تعلیم اور دشمن کا اس پر اعتراض کیا عجیب بات ہے کہ وہی بات جسے دشمن اعتراض کے رنگ میں پیش کرتے ہیں اسی کو خوبی کی دلیل قرار دے کر بیان کیا گیا ہے.دشمن کہتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی صداقتوں کو اسلام اپنے اندر لے آیا ہے.اس لئے و ہ چور ہے.لیکن قرآن کریم اسی اعتراض کو بطور خوبی
Page 249
بیان کرتا ہے.اور فرماتا ہے کہ اسلام بہرے کی طرح نہیں ہے کہ صرف اپنی مخصوص باتوں پر قانع رہے بلکہ وہ سننے والوں کی طرح ہے جو دوسروں کے علوم کو بھی لے لیتے ہیں اور اپنے علم کو کامل کرلیتے ہیں اور اس نے تمام مذاہب کی ایسی تعلیمات کو اپنے اندر جمع کرلیا ہے جو مفید اور نفع رساںہیں اور ان کے علاوہ ایسی صداقتیں بھی پیش کی ہیں جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہیں.کافر و مسلم میں ایک اورطرح کا فرق دوسرے سَمِیْع اور اَصَمّ کا مقابلہ کرکے یہ فرق بھی بتایا ہے کہ اسلام میں الہام الٰہی کا درازہ کھلا ہے.وہی کان سننے والا ہے جو خداتعالی کی آواز کو سنتا ہے اور درحقیقت کان اسی لئے پیدا کیا گیا ہے اور جو کان خدا تعالیٰ کی آواز کو نہیں سنتا وہ بہرہ ہے اور یہی فرق بصیر اور اعمٰی کے مقابلہ میں ظاہر کیا گیا ہے.اسلام میں نشانات اور معجزات کا دروازہ کھلا ہے اور درحقیقت بینا وہی ہے جو اپنے رب کے تازہ نشانات کو دیکھتا ہے جو آنکھ خدا تعالیٰ کے معجزات اور نشانات کو نہیں دیکھتی وہ اندھی ہے.چونکہ جلال الٰہی پردوں میں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی آواز پردوں میں نہیں ہوتی اس لئے سننے کے لئے مبالغہ کا صیغہ یعنی سمیع (بہت سننے والا) استعمال فرمایا ہے اور دیکھنے کے لئے مبالغہ کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا.وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ١ٞ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ اور ہم نے یقیناً نوح کو اس کی قوم کی طرف (رسول بنا کر) بھیجا تھا (جس پر اس نے انہیں کہا تھا) کہ میں یقیناً تمہیں مُّبِيْنٌۙ۰۰۲۶ (کھول) کھول کر آگاہ (اور ہوشیار) کر نے والا (بنا کر بھیجا گیا )ہوں.تفسیر.اندھے اور سوجاکھے کے فرق کی ایک مثال چونکہ اس سے پہلے بیان فرمایا تھا کہ جھوٹے مدعی یا ان کے پیرو نہ سچے اور جھوٹے نبیوں کے انجام کو دیکھتے ہیں اور نہ ان کے حالات سنتے ہیں اور سچوں اور جھوٹوں کی مثال آنکھوں والے اور اندھے سے دی تھی.اب اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے چند مثالوں کو پیش کیا ہے.اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کو لیا ہے فرماتا ہے کہ نوح سچے نبیوں میں سے تھا.اور اس نے نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے حالات پر غور کرو.سچا نبی ہمیشہ مبین ہوتا ہے سچے نبی کی زبردست نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ہوتا ہے.
Page 250
یعنی(۱) اس کی تعلیم مخفی نہیں ہوتی اور وہ چوری چوری کام نہیں کرتا اور کبھی اپنے پیغام کو اور تعلیم کو لوگوں سے چھپاتا نہیں جبکہ جھوٹے مدعی عام طور پر جتھا بندی کے خیال سے اور لوگوں کے بدک جانے کے ڈر سے اپنی تعلیم کو چھپاتے ہیں.اس وقت بھی دیکھ لو کہ باب اور بہاء کی تعلیم کو کس طرح مخفی رکھا جاتا ہے.ان کی کتب کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا جاتا.اور بہائیوں نے باب کی بعض کتب تو تلاش کرکرکے تلف کردی ہیں(کتاب نقطۃ الکاف صفحہ ۲۴۷).(۲) دوسرے سچے نبی کا انذار مبین ہوتا ہے.یعنی بے معنی انذار نہیں ہوتا بلکہ دلائل پر مبنی ہوتا ہے.اور اس وجہ سے وہ انذار مایوسی پیدا کرکے قوم کو اور بھی تباہ نہیں کرتا.جھوٹے نبیوں کے انذار یونہی نقل کے طور پر ہوتے ہیں.اور بے معنی ہوتے ہیں.اور لوگوں میں صرف مایوسی پیدا کرنے کا کام دے سکتے ہیں بلکہ تمام نادان لوگ ایسے ہی بے معنی انذار کے عادی ہوتے ہیں.اور نہیں سمجھتے کہ انذار بھی ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا.کبھی اس کا اثر الٹ پڑتا ہے.غیر مبین انذار لوگوں کے لئے اُلٹا موجب نقصان ہوتا ہے ایسے ہی انذار کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ قَالَ ھَلَکَ النَّاسُ فَھُوَ اَھْلَکَہُمْ(صحیح مسلم کتاب البر و الصلۃ باب النھی عن قول ھلک الناس) جو شخص یہ کہتا پھرے کہ لوگ تباہ ہو گئے.بے ایمان ہو گئے.بے دین ہو گئے دراصل وہی ان کی تباہی و بربادی اور بے ایمانی و کمزوری کا موجب ہوتا ہے.کیونکہ اس سے بے دینی اور بے ایمانی کی اہمیت لوگوں کے دل سے اٹھ جاتی ہے اور مایوسی پیدا ہوجاتی ہے.جب تک کوئی نیا نظام نہ بدلا جائے لوگوں میں یہ احساس نہیں ہونا چاہیےکہ ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں رہا.ورنہ وہ بالکل ہمت ہار بیٹھتے ہیں.ہاں جب ایک نبی آکر نیا نظام قائم کرتا ہے تب انذار عام مضر نہیں ہوتا ایک تو اس لئے کہ واقع میں اس وقت قوم کی حالت خراب ہوچکی ہوتی ہے اور دوسرے اس لئے کہ علاج بھی ساتھ موجود ہوتا ہے.حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ہوں یعنی میرا انذار دلیل پر مبنی ہے.میں قوم کو خراب اور مایوس کرنے کو نہیں آیا بلکہ حقیقت سے آگاہ کرنے کو آیا ہوں.مبین کےمفہوم میں عذاب سے بچنے کے طریق کی طرف بھی اشارہ ہے نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں صرف خالی انذار ہی نہیں کرتا بلکہ اس عذاب سے بچنے کے ذرائع بھی بتاتا ہوں.چنانچہ اسی لئے اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ اس عذاب سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواء کسی کی عبادت نہ کرو.اگر تم ایسا کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے.تو گویا علاج بتا کر اپنا نذیر مبین ہونا ثابت کیا.ظالم بادشاہ کا وجود بھی ملک کے لئے نذیر ہوا کرتا ہے.منافقوں کا گروہ اور استبدادیوں کا گروہ بھی قوم اور ملک کے لئے نذیر ہی
Page 251
ہوتا ہے.نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌصرف نبی ہو سکتا ہے مگر یہ ساری جماعتیں نذیر مبین نہیں ہوا کرتیں.کیونکہ وہ خود نہیں کہتیں کہ ہم نذیر ہیں.بلکہ وہ تو اپنے آپ کو قوم کی ترقی کا موجب بتاتی ہیں.ان کا انذار عملی ہوتا ہے اور پھر اس انذار کی تائید الہام الٰہی سے بھی نہیں ہوتی بلکہ صرف اس قیاس پر مبنی ہوتی ہے کہ چونکہ اس قوم پر ظالم بادشاہ حاکم ہے تو قوم ضرور تباہ ہوگی یا یہ کہ جب ان کے اندر فسادی لوگ پیدا ہوگئے ہیں تو ان کے لئے ہلاکت ضرور مقدر ہے.پس صرف نبی ہی نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ہوسکتا ہے.کیونکہ وہ خود موجب تباہی نہیں ہوتا بلکہ تباہی سے ہوشیار کرنے والا ہوتا ہے.اور اس کے انذار کی بنیاد الہام الٰہی پر اور یقین پرہوتی ہے اور دوسرے انذاروں میں صرف قیاس ہوتا ہے.اَنْ لَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّا اللّٰهَ١ؕ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ (اس پیغام کے ساتھ) کہ تم اللہ (تعالیٰ) کے سوا (کسی ہستی) کی پرستش نہ کرو میں یقیناً تم پر ایک (بڑے) تکلیف يَوْمٍ اَلِيْمٍ۰۰۲۷ (دینے) والے د ن کے عذاب (کے آنے) سے ڈرتا ہوں.تفسیر.عَذَابٌ اَلِیْمٌ کی نسبت عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ فرمایا بعض مفسرین اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ اَلِیْم یَوْمٌ کی صفت کیوں آئی ہے.حالانکہ دکھ تو عذاب کی صفت ہے نہ کہ دن کی(تفسیر طبری زیر آیت ولقد ارسلنا نوحا الی قومہ ).میرے نزدیک یہ ان کی غلطی ہے انہوں نے اس امر کو نہیں سمجھا کہ جس کلام میں عمیق اور حقائق سے پر معارف بیان کئے جائیں گے لازماً اس میں نئے نئے محاورات اور عجیب عجیب ترکیبیں بھی استعمال کرنی پڑیں گی.ورنہ اس کے باریک مطالب کا اظہار نہیں ہوسکے گا.جو شخص بھی غور سے کام لے گا اسے معلوم ہوجائے گا کہ عَذَابٌ اَلِیْمٌ اور عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ میں بڑا فرق ہے.الیم کو یوم کی صفت بنانے سے اس عذاب کی شان زیادہ ظاہر ہوتی ہے.بہ نسبت عذاب کی صفت بنانے کے.الیم کے معنی دکھ دینے والے کے ہیں.بے شک عذاب بھی الیم یعنی دکھ دینے والا ہوتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے.مگر کئی دن بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی یاد ہمیشہ انسانوں کو دکھ دیتی رہتی ہے.اور ہزاروں سال بعد بھی ان کی تکلیف کا خیال کرکے انسان کانپ اٹھتے ہیں.پس یہ امر ثابت ہے کہ بعض دن بھی الیم ہوتے ہیں بلکہ عذاب تو صرف ان لوگوں کے لئے الیم ہوتا
Page 252
ہے جن پر وہ نازل ہوا ہو مگر خطرناک عذابوں کے زمانہ کی یاد بعد میں آنے والوں کے لئے بھی دکھ کا موجب ہوتی رہتی ہے.پس عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ کہہ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ عذاب ہمیشہ یاد رہنے والا اور لوگوں کو ڈراتے رہنے کا موجب ہوگا اور ان معنوں میں جو خوبی اور جدت ہے وہ عَذَاب اَلِیْمٌ کہنے میں ہرگز نہیں ہوسکتی تھی.اور حقیقۃً بھی دیکھو تو آج تک حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ایک ہیبت ناک واقعہ اور وہ دن ایک خوفناک دن سمجھا جاتا ہے.اس دن کا ذکر کرنے سے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں اور دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے.فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا اس پر ان بڑے لوگوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے (اس کا) انکار کیا تھا (اسے) کہا (کہ) ہم تجھے اپنے بَشَرًا مِّثْلَنَا وَ مَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ جیسے ایک آدمی کے سوا (کچھ) نہیں سمجھتے اور نہ ہم( یہ) دیکھتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو سرسری نظر میں ہم اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ١ۚ وَ مَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ میںسے حقیر ترین (نظر آتے) ہیں کسی نے تیری پیروی (اختیار) کی ہو اور ہم اپنے پر تمہاری (کسی قسم کی)کوئی فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ۰۰۲۸ فضیلت نہیں دیکھتے.بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو.حلّ لُغَات.بَشَرٌ.بَشَرًاعُبِّرَعَنِ الْاِنْسَانِ بِالْبَشَـرِاِعْتِبَارًا بِظُھُوْرِ جِلْدِہٖ مِنَ الشَّعْرِ بِخِلَافِ الْحَیْوَانَاتِ الَّتِیْ عَلَیْہَا الصُّوْفُ اَوِالشَّعْرُ اَوِالْوَبَرُ وَاسْتَوٰی فِی لَفْظِ الْبَشَرِالْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَثُنِّیَ فَقَالَ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ وَخُصَّ فِی الْقُرْاٰنِ کُلُّ مَوْضِعٍ اعْتُبِرَ مِنَ الْاِنْسَانِ جُثَّتُہٗ وَظَاھِرُہٗ بِلَفْظِ البَشَرِ انسان کو بشر اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر بال نہیں ہوتے.برخلاف جانوروں کے کہ ان کے جسموں پر بال یا صوف ہوتی ہے.اور بشر کا لفظ واحد اور جمع دونوں کے لئے بولا جاتا ہے.مگر تثنیہ کا صیغہ الگ بنایا جاتا ہے.فرماتا ہے أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ اور قرآن کریم میں جہاں کہیں انسان کے جسم اور شکل کا ذکر کیا گیا ہے.اس کے لئے بشر کا لفظ
Page 253
استعمال ہوا ہے.(مفردات) میرے نزدیک بشر آدمی اور انسان کے الفاظ مختلف لحاظ سے بولے جاتے ہیں.انسان کے لفظ سے اس کی حقیقت اور اس کے اخلاق کو ظاہر کرتے ہیں.بشر کے لفظ سے اس کے ڈھانچے اور ظاہری شکل پر زور دینا مدنظر ہوتا ہے.اور آدمی کے لفظ سے اس کی ابتداء کا اظہار مطلوب ہوتا ہے.أَرَاذِلُ.اَرَاذِلُ اَرْذَلُ کی جمع ہے جو اسم تفضیل کا صیغہ ہے.اس کا فعل رَذُلَ بھی ہوسکتا ہے جس کی مصدر رَذَالۃٌ ہے.اور رَذَلَ بھی.جو متعدی ہے او راس کی مصدر رَذْ لٌ ہے.اور اس مؤخرالذکر صورت میں اَرْذَلُ بمعنی مَرْذُوْلٌ ہوگا.رَذَلَہٗ کے معنی ہیں جَعَلَہٗ رذِیْلًا.اسے رذیل قرار دیا.ضِدُّ اِنْتَقَاہُ اسے ردی ٹھہرایا.انتخاب میں ساقط کر دیا.رد کر دیا.ناپسند کیا.ناقابل پذیرائی قرار دیا.اَلْاَرْذِلُ اَیْضًا اَلدُّوْنُ فِی مَنْظَرِہٖ وَحَالَاتِہٖ کَالرَّذِلِ وَالرَّذِیْلِ اَرْذَلْ کا لفظ علاوہ افعل التفضیل کے معنوں کے اس چیز یا شخص کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو اپنے منظر یا حالات کی رو سے حقیر ہو.اور یہی معنی لفظ رَذِلٌ اور رَذِیْلٌ کے ہیں.یُقَالُ ثَوْبٌ رَذِلٌ وَ رَذِیْلٌ اَیْ وَسْخٌ رَدِیٌّ اور جب یہ الفاظ کپڑے کے لئے بولے جائیں تو ان کے معنی میلے اور ردی کے ہوتے ہیں.(اقرب) بَادِی الرَّأْ ی.بَادٰی کے معنی ظاہر کے ہیں.یہ بَدَایَبْدُو سے نکلا ہے.اور بعض لوگوں نے اسے بَدَءَ یَبْدَءُ سے قرار دیا ہے.اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے شروع والا.پہلا.شروع کرنے والا.پہل کرنے والا.یہ لوگ بَادِیُ الرَّاْیِ کو بَادِيُء الرَّأْیِپڑھنا بھی جائز سمجھتے ہیں.تفسیر.اس اعتراض کا جواب کہ جب کہ ہماری ظاہری شکلیں یکساں ہیں تو باطنی میں فرق کیونکر ہو سکتا ہے؟ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا.یعنی تیری ظاہری صورت و شکل ہم سے ملتی ہے اور تو ہماری ہی طرح کا ایک بشر ہے پھر ہم کیونکر تسلیم کریں کہ باطن میں تو ہم سے مختلف ہے اور کیونکر سمجھیں کہ تیری خدا کے دربار میں رسائی ہو گئی ہے اور کیونکر یقین کرلیں کہ تجھے ایسی طاقتیں ملی ہیں جو ہمیں نہیں ملیں جن کی وجہ سے تو تو خدا کی باتیں سن سکتا ہے اور ہم نہیں سن سکتے؟ انبیاء کے دشمن ہمیشہ سے یہی اعتراض کرتے چلے آئے ہیں اور ان کی دلیل یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان کے کمال کی بنیاد علوم کسبیہ پر ہوتی ہے.جب یہ نبی کسبی علوم نہیں رکھتے تو انہیں خاص طاقتیں کیسے مل سکتی ہیں.حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن بھی یہی دلیل پیش کرکے اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تم کو باطنی طور پر کوئی خاص قوتیں ملتیں تو چاہیےتھا کہ تمہاری ظاہری شکل بھی بدلی ہوئی ہوتی.یعنی علوم ظاہر بھی تم کو خاص رنگ کے عطا ہوتے اور اگر کسبی علوم سے تمہاری عزت نہیں بلکہ خاص موہبت تم کو عطا ہوئی ہے تو پھر باطنی طاقتوں میں فرق کے ساتھ تمہاری ظاہری شکل
Page 254
میں بھی کچھ تغیر چاہیےتھا.مگر یہ تو نظر نہیں آتا.پس ہم کیونکر مان لیں کہ تمہارے باطنی قویٰ ہم سے جدا ہیں.یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑا فلسفیانہ نکتہ بیان کیا ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس دلیل کی تائید میں ہندوؤں کی طرح بزرگوں کی تصویریں دکھاتے ہوں کہ دیکھو نبی ایسے ہوتے ہیں جن کے دس دس سر اور کئی کئی مونہہ ہوں.گنیش جی کی ہندوؤں نے عجیب شکل تجویز کی ہوئی ہے.پہلے زمانہ کے لوگ یہ سمجھ ہی نہ سکتے تھے کہ نبی ظاہری شکل و شباہت میں ہماری طرح کا ایک انسان ہوتا ہے.غرض نوح علیہ السلام کے دشمن یہ دلیل بیان کرکے کہ ظاہر کا باطن کے ساتھ مطابق ہونا ضروری ہے اور باطن کا ظاہر کے ساتھ مطابق ہونا لازم.حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تو نبی ہوتا تو تیری اور ہماری ظاہری شکل و شباہت میں اختلاف لازم تھا.اس زمانہ کے دشمنانِ حق اس دلیل کو سن کر سر دھنتے ہوں گے اور اس پر واہ واہ کا شور بلند ہوتا ہوگا.حالانکہ حقیقت میں یہ بات بالکل فضول اور لچر ہے.حضرت نوح ؑ کے دشمن اس سے آگے بڑھتے ہیں اور مَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ کہہ کر اپنی حجۃ کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں.یعنی وہ کہتے ہیں کہ تو خاص قوتوں سے عاری ہے بلکہ صرف ہماری طرح کا ایک بشر ہے.رہے تیرے مرید سو وہ ہم سے بھی گرے ہوئے اور گئے گزرے ہیں.اب یہ مجموعہ یا معجون مرکب مل کر دنیا میں کیا بنائے گا.بَادِيَ الرَّاْيِ کی ترکیب کے لحاظ سے کئی معنی ہوسکتے ہیں.اول تو یہ کہ اسے اَرَاذِلُنَا کے متعلق سمجھا جائے.اس صورت میں اگر بادی کا لفظ بدء یبدء سے سمجھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پہلی نظر میں تو نوح ؑ کے متبع رذیل ہی نظر آتے ہیں.باطن میں شاید اشراف ہوں تو ہوں.یہ قاعدہ ہے کہ کبھی اپنی بات پر زور دینے کے لئے شبہ کے الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں.اور مطلب اس کے الٹ ہوتا ہے.جیسے کوئی شخص کہے کہ شاید ہم کمینے ہی ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ہرگز ایسے نہیں ہیں.ایسے ہی وہ لوگ حضرت نوح ؑ کے متبعین کے متعلق طنزاً کہتے ہیں کہ پہلی نظر میں تو یہ لوگ رذیل ہی نظر آتے ہیں غوروخوض سے یہ اشراف ثابت ہوں تو ہوں.مطلب یہ کہ ان کے رذیل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوسکتا.اور اگر اس لفظ کو بَدَا یَبْدُو سے سمجھا جائے اور اَرَاذِلُنَا کا متعلق قرار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ظاہری نظر میں تو یہ لوگ کمینے نظر آتے ہیں کوئی ان کی خاص خوبیاں ہوں تو وہ نوح ؑ کو معلوم ہوں گی ہمیں تو نظر نہیں آتیں.اس میں بھی طنز ہے.دوسری صورت یہ ہے کہ بَادِيَ الرَّاْيِ کو اِتَّبَعَکَ کا متعلق قرار دیا جائے.اس صورت میں اس آیۃ کے یہ
Page 255
معنی ہوں گے کہ ہمارے نزدیک تو چند رذیلے لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے.ان کا ایمان اوپرا ایمان ہے.اگر وہ بھی تیری تعلیم کی حقیقت پر غور کرتے تو ہرگز نہ مانتے.گویا اوّل تو تیرے اتباع اَرَاذِلُنَا ہم میں سے عیب دار اور ادنیٰ لوگ ہیں اور پھر انہوں نے تیرے قبول کرنے میں غور و فکر اور سوچ بچار سے کام نہیں لیا.اس رنگ میں انہوں نے حضرت نوح ؑ کی انتہائی تحقیر کی ہے.تیسرے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ ان کی اتباع محض ظاہری ہے یعنی ان لوگوں نے بعض فوائد کے حصول کے لئے صرف ظاہر میں مانا ہے.دل میں یہ بھی ایمان نہیں لائے.گویا تین معنی ہوئے.۱.ہمارا پہلا یا ظاہری خیال تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے تجھے مانا ہے وہ اراذل ہیں.۲.ان لوگوں نے بھی بغیر فکر کے مانا ہے.۳.جن لوگوں نے مانا ہے انہوں نے صرف ظاہر میں مانا ہے حقیقت میں دل سے کسی نے نہیں مانا.مَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ.یعنی ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ کوئی باریک اور مخفی بات ہوگی جس کی وجہ سے خدا نے تمہیں یہ درجہ دے دیا ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ اگر سچ مچ ایسی خوبی تم میں تھی تو کیا اس کے نتیجہ میں تم کو کوئی خاص شان و شوکت نہیں ملنی چاہیےتھی کیونکہ جس کے اندر کوئی خاص قابلیت ہوتی ہے وہ اپنے ہمعصروں پر غالب آجاتا ہے.مگر یہ بات بھی ہمیں نظر نہیں آتی.پھر ان سب دلائل کے مجموعہ کا وہ آخری نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ تم جھوٹے ہو کیونکہ بلاوجہ اور بلاسبب اپنی برتری اور اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو.آہ! یہ ایک قدیم دستور ہے کہ لوگ نبیوں کو اپنے بنائے ہوئے معیاروں پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ ان معیاروں پر پورے نہیں اترتے تو تسکین قلب کے ساتھ یہ خیال کرلیتے ہیں کہ انہوں نے ان کے دعویٰ کو غیرمتعصبانہ طور پر سوچ لیا اور اسے غلط پایا.دنیا اس قدر ترقی کرچکی ہے اور اس قدر انبیاء گزر چکے ہیں لیکن اب بھی انسان خدائی کلام کو اور خدا کے فرستادوں کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ معیار پر پرکھنے کے لئے طیار نہیں بلکہ اپنے غلط خیالات کے مطابق ان کی سچائی کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن کیا اس طرح ہدایت مل سکتی ہے.ہرگز نہیں.
Page 256
قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ اس نے کہا اے میری قوم (ذرا)بتاؤ( تو سہی کہ) اگر (ثابت ہو جائے کہ) میں (اپنے دعویٰ کی بنا) اپنے رب کی اٰتٰىنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ١ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا طرف سے (عطا شدہ) کسی کھلے نشان پر (رکھتا) ہوں اور اس نے اپنے حضور سے مجھے(اپنی ) ایک (بہت بڑی) وَ اَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ۰۰۲۹ رحمت عطا کی ہے اور وہ تم پر مشتبہ رہی ہے.(توتمہارا کیا حال ہو گا) کیا ہم اس (روشن نشان) کو ماننا تم پر (جبراً) واجب کردیں گے اگر چہ تم اسے نا پسند کرتے ہو.حلّ لُغات.اَلْزَمَ اَلْزَمَ فُلَانًا اَلْمَالَ وَالْعَمَلَ اَوْجَبَہٗ عَلَیْہِ اس کے ذمہ ڈال دیا اس کی ادائیگی یا اس پر عمل پیرا ہونا ا سکے ذمہ لازم کر دیا.(اقرب) تفسیر.بلا تحقیق کسی امر سے نفرت رکھنا محرومی کا باعث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے مخالفوں کو توجہ دلائیں کہ تم تھوڑی دیر کے لئے فرض کرلو کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ مجھے اپنے رب کی طرف سے دلائل ملے ہیں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت دی ہے اور پھر یہ بھی فرض کرلو کہ وہ بینات اور رحمت ایسی پیچیدہ صورت میں آئے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آتے تو بتلاؤ کہ کیا بغیر اس کے کہ تم غور کرو ہم تم کو سمجھا سکتے ہیں یعنی کسی حقیقت کے سمجھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس پر غور و فکر کرے اور اسے ایسے راستہ سے سوچے جس کے ذریعہ سے اسے سمجھا جاسکے لیکن تم لوگ تو پہلے ہی اسے ناپسند کرنے لگے ہو.اور سنتے ہی تم نے اسے ردی قرار دے دیا ہے.پھر تمہارے سمجھنے کی کیا صورت رہ جاتی ہے.صرف جبر ہی ہے.سو وہ کیا نہیں جاسکتا.جبری تبلیغ کے عقیدہ کا ابطال اس آیت سے جبری تبلیغ کے عقیدہ کی تردید ہوتی ہے.اور معلوم ہوتا ہے کہ جو دین کو ناپسند کرے اسے جبراً دین نہیں سکھایا جاتا.اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کسی امر کی تحقیق کرنے کی بجائے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں وہ حق سے محروم رہ جاتے ہیں.جو شخص صداقت کا متلاشی ہو اسے چاہیےکہ اپنے دل کو ہمیشہ تعصب سے خالی رکھے اور سچی تلاش کی عادت ڈالے.
Page 257
وَ يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا١ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ اور اے میری قوم میں اس کی بابت تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا اجر اللہ (تعالیٰ) کے سوا(اور) کسی پر نہیں اور میں ان وَ مَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا١ؕ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ لٰكِنِّيْۤ لوگوں کو جو(مجھ پر) ایمان لائے ہیں ہرگز نہیں دھتکاروں گا.وہ (تو) اپنے رب سے ملنے (کاشرف پانے) والے اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ۰۰۳۰ ہیں.بلکہ (اس سےبڑھ کر بات یہ ہے کہ) میں تمہیں ایسے لوگ خیال کرتاہوں جو جہالت سے کام لیتے ہیں.حلّ لُغات.طَرَدَ.طَارِدٌ طَرَدَ سے اسم فاعل ہے.طَرَدَ کے معنی ہیں.ابعد.دور کر دیا.ہٹا دیا.رد کر دیا.(اقرب) تفسیر.مجھے جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ان کے تعصب کی حالت کو بیان کرنے کے بعد حضرت نوح ؑ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عقل مند انسان جو کام کرتا ہے کسی مقصد کے لئے کرتا ہے.اگر میں ویسا ہی ہوں جیسا کہ تم سمجھتے ہو اور جھوٹا کلام بنا کر تم کو سنارہا ہوں تو یہ تو سوچو کہ اس میں میری غرض کیا ہے.کیا میں اس کام میں کوئی فائدہ حاصل کررہا ہوں.تم خوب جانتے ہو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا پھر مجھے جھوٹ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ حکومت بھی مقصود نہیں شاید کوئی شخص کہے کہ گو نوح ؑ اجر طلب نہیں کررہے تھے مگر آخر اپنے ماننے والوں پر حکومت تو کرتے تھے اور کئی لوگ حکومت کے حصول کے لئے جھوٹ بول لیتے ہیں لیکن یہ اعتراض بھی درست نہ ہوگا.اس لئے کہ انبیاء اپنی تعلیم پر دوسروں سے زیادہ عامل ہوتے ہیں.پس وہ کام جسے وہ خود دوسروں سے بڑھ کر کررہے ہوں حاکمانہ فعل نہیں کہلا سکتا.اس صورت میں تو ان کی حکومت بھی خادمانہ حکومت ہی کہلاسکتی ہے جسے کوئی شخص لالچ اور حرص کے تابع قرار نہیں دے سکتا.اپنی برأت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے اتباع کی بریت کرتے ہیں اور پہلا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ظاہر میں ایمان دار ہیں اور جب یہ ظاہر میں ایمان لاچکے تو میرا حق نہیں کہ میں وساوس اور شبہات کی بناء پر انہیں
Page 258
اپنے پاس سے دھتکار دوں اور دور کر دوں.دوسرے یہ کہ جب میں کسی سے کچھ طلب نہیں کرتا تو میرے نزدیک غریب و امیر برابر ہو گئے.پھر میں کیوں انہیں دھتکار وں؟ میرے نزدیک تو ایمان کا سوال ہی اہمیت رکھتا ہے.اور ایمان ان لوگوں کو حاصل ہے.پس جو چیز میری نظر میں عزت ہے جب وہ انہیں حاصل ہے تو تمہارا یہ اعتراض کہ یہ اراذل ہیں میری نظر میں کیا وقعت رکھتا ہے؟ اپنے اتباع کے ایمان و اخلاص کا اثبات دوسرا اعتراض آپ کے مریدوں پر کفار نے یہ کیا تھا کہ یہ لوگ ظاہر میں ایمان لائے ہیں.ان کے دلوں میں ایمان نہیں.اس کا جواب یہ دیا کہ جس طرح میں ان سے کچھ نہیں مانگ رہا یہ لوگ بھی مجھ سے کچھ نہیں لے رہے.پھر میرا کیا حق ہے کہ ان کے ایمان کی نسبت شبہ کروں.یہ خدا تعالیٰ کے فضل کے طالب ہیں اور وہ عالم الغیب ہے.آخر یہ اس کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کی ملاقات ان کو نصیب ہوگی جو ان میں سے جھوٹا ہوگا خدا تعالیٰ خود اس سے مناسب معاملہ کرے گا مجھے اس جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جھوٹا نہیں بلکہ تم بد اخلاق ہو تیسرا اعتراض نوح علیہ السلام کے دشمنوں کا یہ تھا کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ تم جھوٹ بولتے ہو اور اس طرح ادنیٰ درجہ کے لوگ ہو.اس کا جواب یہ دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سچائی سے منہ موڑ رہے ہو.یعنی تم کو یہ خوب معلوم ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں.اور آیا ہم جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں؟ لیکن تم دشمنی کی وجہ سے ان امور کو چھپاتے ہو اور تجاہل سے کام لیتے ہو.حضرت نوح ؑکا اپنی پہلی زندگی کو اپنی سچائی کے ثبوت میں پیش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو نبی بھی آتا ہے اس کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی بھی نہایت ہی راستبازی کی زندگی ہوتی ہے.وہ جھوٹ سے ہمیشہ سے محفوظ چلا آیا ہوتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں ہوسکتے تھے.حضرت نوح علیہ السلام اس جگہ اس امر کو پیش کرتے ہیں کہ میری سچائی کے تو تم بھی قائل ہو ہاں دعویٰ کے بعد دشمنی کی وجہ سے الزام لگانے لگے ہو.مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ کے معنی واصل باللہ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ انہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی لیکن میں تو ان کے چہروں سے محسوس کرتا ہوں کہ وہ لوگ واصل باللہ ہورہے ہیں.تم لوگ خود علم روحانی سے کورے ہو.اسی لئے تمہیں ان کے چہروں سے ایمان نظر نہیں آتا.تم کہتے ہو مَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ کہ ہمیں تمہاری اپنے پر کوئی فضیلت نظر نہیں آتی.حالانکہ خدا کا فضل ہورہا ہے اور یہ لوگ خدا
Page 259
کا قرب حاصل کررہے ہیں.تم نہ دیکھو تو اس میں ان کا کیا قصور ہے.اصل فضیلت وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں فضیلت ہو نادان انسان صرف دنیا کی فضیلت کو فضیلت سمجھتا ہے.خدارسیدہ کے نزدیک اصل فضیلت وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں ہو.حضرت نوح ؑ تو یہ دیکھتے تھے کہ ان کے اتباع قرب الٰہی کی راہوں میں ترقی کررہے ہیں.اور کفار ان کے کپڑوں اور کھانوں کو دیکھ رہے تھے.اس قدر مختلف نقطۂ نگاہوں سے ایک نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا.اس لئے دونوں کے نتیجوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا.ایک جماعت اتباع نوح علیہ السلام کو اراذل دیکھ رہی تھی دوسرا شخص ان کو شریف ترین وجود پاتا تھا.حضرت نوح ؑ کے اتباع کی قربانیاں وَ لٰكِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ سے ان قربانیوں کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے اتباع کررہے تھے.کیونکہ نبی پر ابتداء میں ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی.بلکہ آگ میں کودنے سے کم یہ فعل نہیں ہوتا.پس حضرت نوح ؑ اپنے مخالفین کو توجہ دلاتے ہیں کہ کیا تم لوگ ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے؟ ان کا ایمان اور اخلاص دیکھ کر بھی انہیں کہنا کہ ان کا ایمان صرف ظاہری ایمان ہے کس قدر بے وقوفی کی بات ہے.وَ يٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ١ؕ اَفَلَا اور اے میری قوم اگرمیں ان کو رد کر دوں.تو اللہ کی طرف سے (آنے والی اس فعل کی سزا سے مجھے بچانے کے لئے ) تَذَكَّرُوْنَ۰۰۳۱ کون میری مدد کرے گا پھر کیا تم (پھر بھی) نہیں سمجھتے.تفسیر.آپ کے اتباع پر جو ارذل ہونے کا الزام لگایا گیا تھا اس کا مزید جواب حضرت نوح ؑ اس طرح دیتے ہیں کہ ان کو رذیل کہنے سے تمہاری غرض تو یہی ہے نہ کہ میں ان کو اپنے پاس سے جدا کردوں.لیکن اتنا تو سوچو کہ مجھے تم سے تو کوئی غرض نہیں لیکن خدا تعالیٰ سے غرض ہے پھر یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ میں تمہیں خوش کرنے کے لئے خدا تعالیٰ کو ناراض کرلوں.جب تم لوگوں کی خاطر جو ایمان نہیں لائے میں ایمان لانے والوں کو نکال دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے جو میری نصرت کا سامان پیدا کیا ہے اس کی ناقدری کرنے کے سبب سے یقیناً وہ مجھ سے ناراض ہوگا اور اس کی ناراضگی کے بعد میں اس عظیم الشان فرض کو کس طرح ادا کرسکوں گا.جو اس نے میرے ذمہ لگایا ہے؟
Page 260
وَ لَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآىِٕنُ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ اور میں تم سے (یہ) نہیں کہتا (کہ) اللہ (تعالیٰ) کے خزانے میرے پاس ہیں.اور نہ (یہ کہ) میں غیب کا علم رکھتا لَاۤ اَقُوْلُ اِنِّيْ مَلَكٌ وَّ لَاۤ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْۤ ہوں اورنہ میں (یہ) کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اورنہ میں ان (لوگوں) کے متعلق جنہیں تمہاری آنکھیں حقارت اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا١ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْۤ (کی نگاہ )سے دیکھتی ہیں (یہ) کہتا ہوں (کہ) اللہ (تعالیٰ) انہیں (کبھی) کوئی بھلا ئی نصیب نہیں کرے گا.جو کچھ اَنْفُسِهِمْ١ۖۚ اِنِّيْۤ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ۰۰۳۲ ان کے نفسوں میں ہے اسے اللہ (ہی سب سے) بہتر جانتا ہےاس صورت میں میں یقیناً( یقیناً) ظالموں میں سے ہوں گا.حلّ لُغَات.اِزْدَرٰی تَزْدَرِیْ اِزْدَرَاہُ.اِحْتَقَرَہٗ اسے حقیر سمجھا.وَاسْتَخَفَّ بِہٖ اسے ذلیل سمجھا.(اقرب) تفسیر.بشریت اور نبوت میں کوئی تضاد نہیں مخالفین کے اعتراضوں کا حضرت نوح ؑ ایک نئے پیرایہ میں جواب دیتے ہیں.اور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن میرے دعویٰ اور بشر ہونے میں کوئی مخالفت نہیں ہے.میں تو ایک پیغامبر ہوں.اور پیغامبر کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ان لوگوں سے جن کی طرف وہ بھیجا گیا ہو مختلف الماہیۃ ہو.بلکہ اس کا تو ان سے متحد ہونا ضروری ہے ہاں اگر میں یہ کہتا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی خدائی میرے سپرد کردی ہے تو بے شک تم یہ مطالبہ کرسکتے تھے کہ ہمارے جیسا ایک بشر خدا تعالیٰ کی خدائی کس طرح سنبھال سکتا ہے.مگر مجھے تو یہ دعویٰ ہرگز نہیں بلکہ صرف یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اس علم کو جو وہ بندوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے میرے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے.اِن اَرَاذِلکہلانے والوں کو بڑے بڑے مراتب اور انعامات عطا ہونے والے ہیں دوسرے اعتراض کا جو آپ کے اتباع پر تھا اس طرح مزید جواب دیتے ہیں کہ تم تو ان کے موجودہ حالات پر قیاس
Page 261
کرتے ہو لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا.میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بہتر سے بہتر جزا نہ ملے گی.یہ ایک لطیف پیرایہ ہے اس امر کے کہنے کا.کہ آئندہ بہتر بدلے ان کو ملنے والے ہیں.اس قسم کا کلام ایکتعریضی اثر رکھتا ہے اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے.چنانچہ اگلے حصہ آیت میں آپ اس کی تفصیل بھی کردیتے ہیں کہ رذیل تو وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل گندہ ہو اور دل کا حال خدا جانتا ہے.تم ظاہری حالت پر قیاس کرتے ہو حالانکہ ظاہری غربت سے انسان رذیل نہیں بنتا.بلکہ دل کی ناپاکی سے رذیل بنتا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو دیکھنے والا ہے اس لئے اگر یہ رذیل نہ ہوئے یعنی دل کے گندے نہ ہوئے تو یقیناً وہ ان کو ان کی خدمات کے صلہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ دے گا.کسی کے ظاہر کے خلاف اس پر فتویٰ لگانا ظلم ہے آخری حصہ میں بتا دیا کہ ناحق دعویٰ کرنے والا یا کسی شخص پر بلاوجہ فتویٰ لگا دینے والا ظالم ہوتا ہے.پس میں تو نہ اپنی نسبت وہ باتیں کہتا ہوں جن کا مجھے حق نہیں اور نہ مومنوں پر ان کے ظاہر کے خلاف فتویٰ لگانے کے لئے تیار ہوں.افسوس! کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو ظاہر کے خلاف فتویٰ لگانے سے اس قدر اجتناب کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ جن کے لئے زیادہ خوف کا مقام ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خطرناک سے خطرناک اتہام لگانے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں.ظلم کسی کا حق دوسرے کو دے دینے کا نام ہے.پس مطلب یہ ہے کہ اگر میں پہلی بات کہوں تو اس صورت میں خدا کا حق اپنے آپ کو دینے والا بن جاؤں گا.اور دوسری بات کہوں تو میں مومنوں کا حق چھیننے والا قرار پاؤں گا.گویا دونوں صورتوں میں میں ظالم بن جاؤں گا.قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَا لَنَا فَاْتِنَا بِمَا انہوں نے کہا( کہ) اے نوح تو ہم سے (خوب) بحث کر چکا ہے.اور تو ہم سے بہت (دفعہ) بحث کر چکا ہے.اب تو تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۰۰۳۳ اگرراستبازوں میں سے ہے تو (باتوں کو جانے دے اور) جس (عذاب) کاتو ہمیںوعدہ دیتا ہے اسے ہم پر لے آ.تفسیر.چونکہ اوپر کی آیات میں حضرت نوح ؑ نے اشارۃً مومنوں کی ترقی کی پیشگوئی کی تھی اور یہ ظاہر امر تھا کہ مومن تبھی ترقی کرسکتے تھے جبکہ ان کے دشمن ہلاک ہوکر ان کے لئے راستہ صاف کریں.اس لئے کفار نے
Page 262
سمجھ لیا کہ اس میں ہماری ہلاکت کی بھی خبر ہے اور مطالبہ پیش کردیا کہ اچھا بحث جانے دو یہ بتاؤ کہ جو تم نے ہماری ہلاکت کی خبر دی ہے وہ کب پوری ہوگی؟ قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَ مَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ۰۰۳۴ اس نے کہا اسے (صرف)اللہ ہی اگر چاہے گا تو لائے گا اور تم (اسے اس کے لانے سے )ہر گز عاجز نہیں کر سکتے.تفسیر.وعیدی پیشگوئیوں کے متعلق تین اصول حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ سمجھ تو تم ٹھیک گئے ہو لیکن عذاب کا لانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں.اس آیت میں وعیدی پیشگوئیوں کی نسبت تین اصل بتائے ہیں.اول یہ کہ ان کے اوقات عام طور پر مخفی رکھے جاتے ہیں.دوسرے یہ کہ وہ ٹل سکتی ہیں کیونکہ ان شاء کہہ کر بتادیا ہے کہ عذاب کی خبر مل بھی جائے تب بھی مشیت الٰہی سے معلق رہتی ہے.تیسرے یہ کہ تفصیلی پیشگوئیاں خواہ ٹل بھی جائیں اصولی فیصلہ کہ خدا تعالیٰ کے بندے غالب ہوکر رہیں گے نہیں بدلتا.تبھی فرمایا کہ خدا چاہے گا تو عذاب آجائے گا لیکن بہرحال خواہ عذاب آئے یا نہ آئے تم لوگ مومنوں پر غالب نہیں آسکتے اور اللہ تعالیٰ کے کام میں روک نہیں بن سکتے.وَ لَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْۤ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ اوراگر میں( ذاتی طور پر) تم سے خلوص (کا تعلق) رکھنا چاہوں (بھی) تو میرا (تم سے) خلوص رکھنا تمہیں (اللہ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ١ؕ هُوَ رَبُّكُمْ١۫ وَ اِلَيْهِ کے عذاب سے بچنےکے لئے) کوئی نفع نہیں پہنچا ئے گا.اگر اللہ( تعالیٰ یہ) چاہتا ہو کہ تمہیں ہلاک کرے وہ تمہارا تُرْجَعُوْنَؕ۰۰۳۵ رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے.حلّ لُغَات.نَصَحَ.نُصْحِیْ نَصَحَہٗ وَ نَصَحَ لَہٗ نَصْحًا وَنُصْحًا وَنَصَاحَۃً وَ نَصَاحِیَۃً یَنْصَحُہٗ.اَیْ وَعَظَہٗ.اسے نصیحت کی.وَاَخْلَصَ لَہٗ المَوَدَّۃَ.اور اس سے بغیر ملونی کے محبت کی.وَالْاَفْصَحُ بِصِلَۃِ اللَّامِ
Page 263
اور اس لفظ کو لام کے صلہ سے استعمال کرنا زیادہ فصیح ہے.غَوٰی یُغْوِیَکُمْ غَوٰی یَغْوِیْ غَیًّا.ضَلَّ وَخَابَ وَانْھَمَکَ فِی الْجَھْلِ وَھَلَکَ گمراہی.ناکامی اور جہالت میں پڑ کر تباہ ہو گیا.غَوِیَ غَوَایَۃً ضَلَّ.گمراہ ہو گیا.اَغْوَاَہُ اَضَلَّہٗ اَغْوَاہُ کے معنی اسے برباد اور ہلاک کر دیا.(اقرب) تفسیر.حضر ت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے بے شک تمہاری ہدایت کی خواہش ہے اور میں تم سے بہت اخلاص رکھتا ہوں مگر میرا اخلاص خدا کی محبت سے جو تمہارا رب ہے بڑھ کر نہیں ہوسکتا.جب وہ دیکھے کہ تمہارا ہلاک ہونا ہی ٹھیک ہے تو پھر میرے ارادے تو اس کے تابع ہیں.حضرت نوح ؑ نے اپنی قوم پر خودبخود بددعا نہیں کی تھی یہ آیت نہایت واضح طور پر اس اعتراض کو رد کرتی ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح ؑ نے خود بددعا کی.حضرت نوح ؑ نے بددعا نہیں کی بلکہ خدا تعالیٰ نے خود کروائی.وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا ہلاک کرنا چاہے تو میں کیا کرسکتا ہوں.پھر ھُوَرَبُّکُمْ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر سے بھی اعتراض کو دور کر دیا.اور یہ بتا دیا کہ جب اس نے جو تمہارا رب ہے تمہاری ہلاکت کا فیصلہ کیا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب تمہاری ہلاکت ہی تمہارے لئے اور دوسروں کے لئے مفید ہے.اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ١ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَ کیا وہ کہتے ہیں (کہ) اس نے اس (وعدہ عذاب وغیرہ) کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے.تو( انہیں) کہہ اگر میں نے اَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَؒ۰۰۳۶ اسے اپنےپاس سے گھڑ لیا ہے تو میرا یہ خطر ناک جرم( ضرور) مجھ پر (ہی وبال بن کر) پڑے گا.اور (تمہارے جرموں کا وبال مجھ پر نہیں ہو گا کیونکہ) جو خطرناک جرم تم کرتے ہو ان سے میں بے زار ہوں.حلّ لُغَات.اِجْرَامٌ.اِجْرَامٌ اَجْرَمَ کی مصدر سے ہے.جس کے معنی ہیں اَذْنَبَ گناہ کیا.عَظُمَ جُرْمُہٗ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا.(اقرب) پس اِجْرَام کے معنے ہوئے بہت بڑا گناہ کرنا.تفسیر.اس آیت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کا ذکر ہے نہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرق صرف یہ ہے کہ پہلے تو حضرت نوح ؑ لوگوں کومخاطب کرتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا
Page 264
ہے کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ سب امور اپنے پاس سے بنا رہا ہوں تو یہ تو ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے.اور اس کی سزا مجھے ملے گی پس تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور اگر میں سچا ہوں تو تمہارا انکار بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے اس کی سزا تم کو ملے گی اور مجھے اس سے کوئی خوف نہیں.حضرت نوح ؑ کا دعوائے عصمت ’میں تمہارے جرموں سے بری ہوں‘ کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام نے افتراء کے الزام کا ایک اور بھی لطیف جواب دیا ہے جو یہ ہے کہ تم لوگ ذرا غور تو کرو کہ تمہاری قوم میں جتنے گناہ پائے جاتے ہیں میں ان سب سے پاک ہوں.پھر کس طرح ممکن تھا کہ خدا پر جھوٹ باندھنے کا جو بدترین گناہ ہے اس کا میں مرتکب ہو جاتا.کیا عقل اس بات کو تسلیم کرسکتی ہے؟ ہرگز نہیں.پس افتراء کا الزام بالکل باطل ہے.اس جگہ پر ویری صاحب نے ایک اعتراض کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح مراد ہیں اور انہی کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے.بلکہ اصل بات یہ ہے کہ (نعوذباللہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بنایا کرتے تھے.بناتے بناتے اس جگہ بھول گئے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں یا نوح کی اور جھٹ کہہ دیا اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ الٓایۃ میرے نزدیک معنی تو وہی صحیح ہیں جو میں اوپر بیان کر آیا ہوں لیکن ویری صاحب کا کلام پڑھنے کے بعدمیں ان معنوں کو بھی صحیح سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اس میں اللہ تعالیٰ نے ویری صاحب کے اعتراض ہی کا جواب دیا ہے اور وہ اس طرح سے کہ ویری صاحب نے آیت وَلَااَقُوْلُ لَکُمْ عِنْدِیْ خَزَائِنُ اللّٰہِ(ہود:۳۲)وغیرہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اعتراض نوح علیہ السلام پر نہیں ہوئے تھے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے تھے مگر انہوں نے ان کا جواب حضرت نوح کی زبان سے دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ایسے اعتراض ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں کوئی نئے اعتراض نہیں ہیں.گویا ویری صاحب نے اس اعتراض میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کا الزام لگایا ہے پس بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب ہے پہلے ہی سے اس جگہ جملہ معترضہ کے طور پر ویری صاحب اور ان کی طرح کے دوسرے معترضوں کا جواب دے دیا ہو.اور فرما دیا ہو کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آئندہ زمانہ میں بعض لوگ پچھلی باتوں پر اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ نوح ؑ کی کہی ہوئی نہیں بلکہ تو نے اپنے پاس سے بنائی ہیں.تو بھی ان کو یہ بات جواب میں کہہ دے کہ اگر میں مفتری ہوں تو اس کی سزا خدا سے پاؤں گا.اور اس سے بچ نہیں سکتا.مگر واقعات نے بتلا دیا کہ جسے ویری صاحب خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اسے تو دشمن پھانسی پر لٹکانے میں کامیاب ہو گئے لیکن جسے وہ مفتری قرار دیتے ہیں وہ اپنے دشمنوں پر غالب آ گیا.کیا مفتری کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ اسی طرح اپنے زمانہ کے
Page 265
تمام عیبوں اور نجاستوں سے پاک ہونے کی وجہ سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ پر مہر صداقت ثبت ہوتی ہے.وَ اُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جو (لوگ) ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا تیری قوم میں سے (اب) کوئی (اور شخص تجھ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَۚۖ۰۰۳۷ پر) قطعاً ایمان نہیں لائے گا اس لئے جو (کچھ) وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو افسوس نہ کر.حلّ لُغات.اِبْتَأَسَ.اِبْتَأَسَہٗکَرِھَہٗ.ناپسند کیا.حَزِنَ افسوس کیا.لَاتَبْتَئِسْ لَاتَحْزَنْ وَلَاتَشْتَکِ.یعنی لَاتَبْتَئِسْ کے معنی ہیں غم نہ کر.اور شکایت نہ کر.(اقرب) تفسیر.حضرت نوح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لئے بددعا نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لاچکے سو لاچکے.آئندہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے صاف پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو جسے بددعا کہا جاتا ہے اگر بددعا ہی سمجھا جائے تو بھی وہ خدا کے حکم کے ماتحت تھی کیونکہ اس آیت کے آخر میں فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ الہام ہوا تھا اس وقت تک حضرت نوح ؑ اپنی قوم کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوئے تھے.اور ان کی حالت پر غمگین تھے کہ اس وقت تک وہ ایمان کیوں نہیں لائے.اب اگر یہ خیال کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا یعنی رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا (نوح :۲۷) بددعا تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس الہام سے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے پہلے کی تھی یا بعد کی.اگر بعد کی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بد دعا نہ رہی بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے فیصلہ پر ایک قسم کا اظہار تسلیم تھا کیونکہ اگر خدا تعالیٰ لوگوں کی تباہی کا فیصلہ پہلے ہی کرچکا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کو بددعا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ دعا اس الہام سے پہلے کی ہے تو پھر بھی بات نہیں بنتی کیونکہ اگر حضرت نوح ؑ اس الہام سے پہلے ہی اپنی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی دعا کررہے تھے تو اس آیت میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اب تیری قوم ایمان نہیں لائے گی.لیکن تو اس مشیت الٰہی پر غم نہ کر جو شخص پہلے ہی قوم کی تباہی کی دعا کررہا تھا اس نے قوم کی تباہی کی خبر سن کر غم کیوں کرنا تھا وہ تو خوش ہوتا.
Page 266
غرض دونوں صورتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں.ٹھیک نہیں بنتیں اور اصل بات یہی ہے کہ آیت مذکورہ کا الہام پہلے کا ہے اور دعا بعد کی ہے اور بطور بددعا نہیں بلکہ الٰہی فیصلہ کی تصدیق کے رنگ میں ہے.گویا حضرت نوح علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو ان کو جس طرح تو نے فیصلہ کیا ہے تباہ کر دے میں تیری رضا پر راضی ہوں.اور اگر اس کا نام بددعا بھی رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت بددعا ہے اور ایسی بددعا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو نبی کی شان کے خلاف نہیں کیونکہ جب علیم و خبیر خدا کسی قوم کی خراب حالت کو ظاہر کردے تو پھر ہدایت سے محروم رکھنے کی دعا صرف واقعات کا اظہار رہ جاتی ہے.حضرت نوح نے یہ دعا کیوں کی اگر یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ تو فیصلہ کر ہی چکا تھا پھر حضرت نوح ؑ کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض وقت نبی کو عذاب کی خبر تو معلوم ہو جاتی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر اپنی قوم کے لئے سفارش کرتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ وعید کو ٹلا دے.حضرت نوح ؑ بھی اسی طرح کرتے رہے.یہاں تک کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ عذاب میں تاخیر کرنے سے خود دین کو نقصان ہوگا تب انہوں نے دعا کی کہ خدا تعالیٰ اپنے اس فیصلہ کو جو وہ کرچکا ہے جاری کردے.وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا وَ لَا تُخَاطِبْنِيْ فِي اور تو ہماری آنکھوں کے (سامنے) اور ہماری وحی (کے حکم) کے مطابق کشتی بنا.اور جن لوگوں نے ظلم (کا شیوہ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا١ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ۰۰۳۸ اختیار) کیاہے.ان کے متعلق مجھ سے (کوئی) بات نہ کرنا.وہ ضرور( ہی) غرق کئے جائیں گے.حلّ لُغَات.فُلْکٌ.اَلْفُلْکُ.اَلسَّفِیْنَۃُ.کشتی یہ لفظ کبھی مذکر استعمال ہوتا ہے کبھی مؤنث (اقرب).عَیْنٌ اَعْیُنٌ عَیْنٌ کی جمع ہے اور عین ان لفظوں میں سے ہے جن کے عربی زبان میں بہت کثرت سے معنی پائے جاتے ہیں.اَلْعَیْنُ الْبَاصِرَۃُ اس کے معنی آنکھ کے ڈھیلے کے بھی ہیں.وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَی الْحَدَقَۃِ اور اس کے معنی آنکھ کی سیاہی کے بھی ہوتے ہیں.وَالْاِصَابَۃُ بِالْعَیْنِ اور نیز اس کے معنی ہیں نظر لگانا.وَاَھْلُ الْبَلَدِ ایک شہر کے لوگ وَاَھْلُ الدَّارِ.ایک گھر کے لوگ.ایک کنبہ.وَالْاِصَابَۃُ فِی الْعَیْنِ یُقَالُ بِہٖ عَیْنٌ.آنکھ کی بیماری کو بھی عین کہتے ہیں.(اردو میں بھی یہ محاورہ ہے کہ آنکھیں آگئیں).اَلدِّیدْبَان.خبررسان.اَلْجَمَاعَۃُ.جماعت، گروہ.
Page 267
حَاسَّۃُ الْبَصَرِ.نظر.اَلْحَاضِرُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ جو چیز آنکھ کے سامنے ہو.خِیَارُا الشَّیْءِ.اچھی چیز.اَلدِّیْنَارُ.سونے کا سکہ.نَفْسُ الشَّیْءِ.کسی چیز کا وجود.اَلنَّقْدُ الْحَاضِرُ.نقدی جو موجود ہو.اَلسَّیِّدُ قوم کا سردار.الشَّمْسُ.سورج.اَوْشُعَاعُہَا.دھوپ.سورج کی روشنی.سورج کی کرنیں.اَلْعَتِیْدُ مِنَ الْمَالِ جو مالیت والی چیز موجود ہو.مال.مَطَرُ اَ یَّامٍ لَایُقْلِعُ کئی دن تک لمبی چلی جانے والی بارش.اَلْیَنْبُوْعُ.چشمہ اور کہتے ہیں کہ اَنْتَ عَلٰی عَیْنِیْ اَیْ فِی الْاِکْرَامِ وَالْحِفْظِ.یعنی جب کہیں.اَنْتَ عَلٰی عَیْنِیْ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تو میری حفاظت میں ہے.اور میں تیری عزت کرتا ہوں.(اقرب) فُلَانٌ بِعَیْنِیْ.اَیْ اَحْفَظُہٗ وَاُرَاعِیْہِ یعنی میں اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہوں.اِنَّکَ بِاَعْیُنِنَا وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِاَعْیُنِنَا اَیْ بِـحِفْظِیْ یعنی ان دونوں آیتوں میں اَعْیُنِنَا سے مراد حفاظت الٰہی ہے وَمِنْہُ عَیْنُ اللہِ عَلَیْکَ اَیْ کُنْتَ فِی حِفْظِہٖ یعنی تو اس کی حفاظت میں رہے.(مفردات) تفسیر.بِاَعْيُنِنَا کے معنی جب حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی تباہی کی خبر دی گئی تو ساتھ ہی یہ حکم ملا کہ ہمارے حکم کے ماتحت کشتی تیار کرو اور اس میں اپنے اتباع سے یا گھر والوں سے مدد لو.حل لغات میں بتایا جاچکا ہے کہ عین کے معنی گھر کے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں اور نبی کے گھر کے لوگوں میں نہ صرف اس کے عزیز شامل ہوتے ہیں بلکہ بسا اوقات اس کے اتباع بھی اس کے گھر کے لوگ ہی کہلاتے ہیں.کیونکہ اس کے سب رشتے روحانی ہوجاتے ہیں.جسمانی رشتوں میں سے بھی وہی اس کے رشتہ دار رہتے ہیں جو روحانی طور پر اس سے تعلق رکھتے ہوں.پس بِاَعْيُنِنَا سے مراد ہمارے گھر والے یا اتباع بھی ہوسکتے ہیں.اور یہ جو فرمایا کہ ہمارے گھر والے سو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے بلکہ چونکہ نبی سے تعلق رکھنے والے خدا تعالیٰ کے بھی پیارے ہوجاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف منسوب کرلیا ہے.جیسے فرماتا ہے فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ.وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ(الفجر:۳۰،۳۱).پس خدا تعالیٰ کے گھر والوں سے مراد اس کی جنت کے مستحق لوگ ہیں اور ان الفاظ میں اس عذاب کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مزید تسلی دی ہے.دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ ہماری قسم قسم کی حفاظتوں میں رہ کر تو یہ کام کر.کیونکہ عین کے معنی جیسا کہ اوپر بتایا جاچکا ہے حفاظت کے بھی ہوتے ہیں اور عزت کے بھی.ان معنوں کے رو سے یہ مراد ہوگی کہ کشتی بناتے وقت لوگ تمسخر کریں گے.ہنسی اڑائیں گے تکلیفیں دیں گے لیکن ہماری حفاظت اور ہماری طرف سے اعزاز تجھے عطا ہوگا پس تو ان کی باتوں کی پرواہ نہکیجیئو.
Page 268
میرے نزدیک بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا سے دو کشتیوں کی طرف اشارہ کیا ہے.ایک وہ کشتی جو مومنوں کی مدد سے تیار ہونی تھی اور دوسری جو وحی سے تیار ہونی تھی.پہلی سے مراد جسمانی کشتی ہے اور دوسری سے مراد روحانی کشتی ہے.یعنی تقویٰ جو انسان کو عذاب الٰہی سے بچالیتا ہے.لَا تُخَاطِبْنِيْ کی دلالت کہ اپنی طرف سے حضرت نوح نے بددعا نہیں کی تھی یہ جو فرمایا ہے کہ ظالموں کے بارہ میں مجھ سے کچھ نہ کہیو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح ؑ نے بددعا اپنی طرف سے نہیں کی تھی.اگر وہ بددعا کررہے ہوتے تو انہیں دعا کرنے سے روکنے کی کوئی ضرورت نہ تھی.وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ١۫ وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ اور وہ کشتی بناتا تھا اور جب بھی اس کی قوم میں سے کوئی بڑے لوگوں کی جماعت اس کے پاس سے گذرتی سَخِرُوْا مِنْهُ١ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ تو اس پر ہنستی (جس پر) اس نے (ان لوگوں سے) کہا(کہ) اگر (آج) تم (لوگ) ہم پر ہنستے ہو.تو( کل) ہم كَمَا تَسْخَرُوْنَؕ۰۰۳۹ (بھی) تم پر ہنسیں گے جیسا کہ (آج) تم( ہم پر) ہنستے ہو.حلّ لُغَات.سَـخِرَسَخِرَ مِنْہُ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کسی فعل کی جزا کے لئے بھی وہی لفظ بول دیتے ہیں.جو اس فعل کے لئے بولا گیا ہو.قرآن کریم میں یہ محاورہ متعدد جگہ استعمال کیا گیا ہے.جیسے جَزَآءُ سَیِّئَۃٍ سَیِّئَۃٌ مِثْلُھَا اور فَاعْتَدُوْا عَلَیْہِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَی عَلَیْکُمْ یہ بات ظاہر ہے کہ ہر امر کی سزا کو زیادتی کرنا نہیں کہا جاسکتا.بلکہ زیادتی کرنا جرم سے زیادہ سزا دینے کو کہتے ہیں مگر باوجود اس کے یہاں برابر کی سزاء کا نام بھی اعتداء رکھا گیا ہے.اسی طرح ایک شاعر کا قول ہے وَدَاوَوْا بِالْـجُنُوْنِ مِنَ الْجُنُوْنِ (دیوان الحماسۃ من باب الحماسۃ وقال أبوالغول الطھوی).مطلب یہ کہ دشمنوں نے اپنی طاقت کا اندازہ صحیح نہ کرکے اور اس زبردست مقام پر حملہ کرکے اپنے جنون کا ثبوت دیا حالانکہ طاقتور کا کمزور پر حملہ کرنا جنون نہیں ہوتا.بلکہ کمزور کا طاقتور پر حملہ کرنا جنون کہلاتا ہے مگر یہاں پر جنون کی سزا کے لئے بھی جنون کا لفظ بول دیا گیا ہے.
Page 269
تفسیر.ضروری ہے کہ انبیاء کی بعض باتوں کو دنیا کے لوگ ماننے کے لئے تیار نہ ہوں جب کبھی بھی خدا تعالیٰ کے مامور دنیا میں آتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑانا چاہتے ہیں اور چونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے ماننے کے لئے ابھی دنیا تیار نہیں ہوتی اس لئے دشمنوں کو اور زیادہ ہنسی کا موقع مل جاتا ہے.نادان لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر غیر معمولی کام ان کے ذمہ نہ لگایا گیا ہو جس کا سمجھنا انسانی عقل سے بالا ہو تو اللہ تعالیٰ کو مامور بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب باوجود عقل کے انسان اپنی مصیبتوں سے آزاد نہیں ہوسکتا اور جب اس کی عقل اپنے گرد و پیش کے حالات پر قیاس کرکے جو علاج سوچتی ہے وہ اس کی ترقی کا موجب نہیں بلکہ اس کی ہلاکت کا موجب ہوتا ہے تبھی تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور آتے ہیں اور چونکہ ان کا علاج بالکل نرالا ہوتا ہے لوگوں کو طبعاً ان کی بات غیرمعقول معلوم ہوتی ہے اور دشمنوں کو شرارت اور ہنسی کا موقع مل جاتا ہے.لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے یہی کہ انبیاء اور ان کی جماعتیں تو کامیاب ہوجاتی ہیں اور ان کے دشمن ہمیشہ کے لئے بے وقوفوں میں شامل ہوجاتے ہیں.فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ١ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ يَحِلُّ پھر جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا( کہ) وہ کون (فریق) ہے جس پر ایساعذاب آرہا ہے جو اسے رسوا کردے گا.اور عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ۰۰۴۰ جس پر ڈیراڈال دینے والا عذاب نازل ہو رہا ہے.حلّ لُغَات.اَخْزٰی اَخْزَاہُ اِخْزَاءً.اَوْقَعَہٗ فِی الْـخِزْیِ وَاَھَانَہٗ.اس کو رسوائی میں مبتلا کر دیا.ذلیل کردیا.اَللہُ فُلَانًا فَضَحَہٗ جب خدائےتعالیٰ فاعل ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس نے اس کی پردہ دری کی.(اقرب)یَـحِلُّ عَلَیْہِ اَوْیُــحَلُّ عَلَیْہِ یَـجِبُ عَلَیْہِ وَیَنْزِلُ.اس پر واجب ہوجائے گا اور نازل ہوگا.(منجد) تفسیر.عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ.عذاب کئی قسم کے ہوتے ہیں.ایک ایسےعذاب کہ جن کے آنے سے دوسرے لوگوں کو عذاب پانے والوں پر رحم آتا ہے جیسے کسی کا مکان گرجائے تو سب لوگ اس پر رحم کرتے ہیں.ایسے عذابوں کے ساتھ رسوائی کا پہلو نہیں ہوتا.مگر بعض عذاب رسوائی کا پہلو بھی ساتھ رکھتے ہیں.جیسے مثلاً یہ کہ کسی شخص کا جھوٹ کھل جائے یہ عذاب بھی ہے اور اس کے ساتھ رسوائی بھی ہے.یا مثلاً ایسا عذاب ہو کہ اسے لوگوں سے بطور عبرت کے یاد رکھوایا جائے جیسے قوم نوح ؑ کا عذاب کہ آج تک لوگوں میں اس کی یاد قائم ہے.
Page 270
ہماری تکلیف وقتی ہے اور تمہاری دائمی عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ایسا عذاب جو قائم رہے گا یعنی اس دنیا میں آئے گا اور اگلے جہان میں بھی جاری رہے گا.یعنی فرمایا کہ عذاب تو وہی ہے جس میں قائم رہنے والی اور حقیقی ذلت ہو.جو مٹنے والی نہ ہو.بلکہ تباہ کردینے والی ہو.پس تمہاری ہنسی سے ہماری کوئی تذلیل نہیں ہوتی اور نہ ہم اس سے گھبراتے ہیں.گھبرانا تو تم کو چاہیےکہ جن پر حقیقی اور دائمی ذلت اور عذاب آنے والا ہے.حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَ فَارَ التَّنُّوْرُ١ۙ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ یہاں تک کہ جب ہمارا (عذاب کا) حکم آجائے اور چشمے پھوٹ کر بہہ پڑیں تو (اس وقت) ہم فرمائیں گے (کہ) كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَ اَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اس میں ہر ایک (قسم کے جانوروں) میں سے ایک جوڑا یعنی دو( ہم جنس فردوں) کو اور اپنےاہل (و عیال) کو وَ مَنْ اٰمَنَ١ؕ وَ مَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ۰۰۴۱ ( بھی) سوائے اس( فرد) کے جس (کی ہلاکت کے متعلق اس عذاب کے آنے) سے پہلے (ہی ہمارا قطعی) فرمان جاری ہو چکا ہو اور( نیز) جو (لوگ تجھ پر )ایمان لائے ہیں انہیں اس میں سوار کر لے اور اس کے ساتھ (رہائش اختیار کرتے ہوئے)سوائے قلیل (تعداد) کے کوئی اس پر ایمان نہ لایا تھا.حلّ لُغَات.فَارَ.فَارَجَاشَ ابل پڑا (قاموس) فَارَتِ الْقِدْرُ.غَلَتْ.ہنڈیا کو ابال آ گیا.فَارَالْمَاءُ نَبَعَ مِنَ الْاَرْضِ وَجَرٰی.جب یہ لفظ پانی کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں پانی زمین میں سے پھوٹ پڑا اور بہہ پڑا (اقرب).اَلتَّنُّوْرُ.اَلتَّنُّوْرُ الْکَانُوْنُ یُخْبَزُفِیْہِ.تنور جس میں روٹیاں پکاتے ہیں.کُلُّ مَفْجَرِ مَآءٍ.جہاں سے پانی پھوٹے.یعنی چشمہ.مَحْفَلُ مَاءِ الْوَادِیِّ.وادی کے پانی کے جمع ہونے کی جگہ.(اقرب) اَلتَّنُّوْرُ وَجْہُ الْاَرْضِ.تنور کے معنی سطح زمین کے بھی ہیں.(تاج ) بحرمحیط کے مصنف کہتے ہیں کہ قرآن میں فَارَالتَّنُوْرُ ہوسکتا ہے کہ مجازاً استعمال ہوا ہو جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حَمِیَ الْوَطِیْسُ جس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ جنگ خوب تیز ہو گئی ہے.حالانکہ لفظ یہی تھے کہ تنور گرم ہو گیا ہے اور فَارَ اور حَـمِیَ کے معنی ایک ہی ہیں.
Page 271
چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّ هِيَ تَفُوْرُ.(الملک :۸) کافر دوزخ کی آواز سنیں گے اور وہ جوش میں آرہی ہوگی.پس اس صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ پانی چاروں طرف پھیل گیا.(بحرمحیط زیرآیت مذکورہ) زَوْجٌ زَوْجٌ کے معنی ہیں کُلُّ وَاحِدٍ مَعَہُ اٰخَرُ مِنْ جِنْسِہِ ہر اک وہ چیز جس کے ساتھ اس کی جنس میں سے ایک اور وجود بھی ہو (اقرب) پس زوج کے معنی ساتھ کے جوڑے کے ہوتے ہیں.نہ کہ دو دو چیزوں کے اور اسی وجہ سے اِثْنَیْنِ کا لفظ لگا کر واضح کر دیا گیا ہے کہ مراد دو ہم جنس جانور ہیں نہ کہ دو جوڑے یعنی چار جانور.حضرت نوح ؑ کو حکم تھا کہ ضروری جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ اپنے ساتھ رکھ لیں.تفسیر.پانی کا عذاب آسمانی اور زمینی دونوں قسم کا جمع ہو گیا تھا یعنی یہ جواب وسوال اور دشمنوں کی طرف سے ہنسی اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے صبر اور توکل کا اظہار اسی طرح ہوتا چلا گیا.یہاں تک کہ چشموں کی جگہوں سے پانی پھوٹ پڑا.یا یہ کہ سطح زمین پر پانی بہنے لگا.یہ عذاب جو حضرت نوح ؑ کی قوم پر آیا صرف کسی زمینی چشمہ کے پھوٹنے کے سبب سے نہ تھا بلکہ جیسا کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے ظاہر ہے اصل سرچشمہ پانی کا بادل تھے.عذاب سے قبل اس قدر بارش ہوئی کہ سب جگہ پانی ہی پانی ہو گیا.اور جیسا کہ کثرت بارش کے وقت میں ہوا کرتا ہے.زمین کے سوتے بھی جاری ہو گئے اور اس آسمانی اور زمینی پانی نے مل کر اس علاقہ کو تباہ کر دیا.سورۂ قمر رکوع اول میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ(القمر:۱۳).اور ہم نے زمین میں چشمے پھوڑ دیئے اور پانی مقررہ امر کے لئے اس میں مل گیا.یعنی آسمانی پانی زمینی پانی سے مل کر دنیا کو تباہ کرنے لگا.اسی سورۃ یعنی ہود میں چند آیات آگے چل کر فرمایا ہے يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ يٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ (ھود:۴۵) اس میں بھی بارش کا ذکر ہے اور سورۂ قمر میں ہےفَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ (القمر:۱۲) اس پر ہم نے آسمان کے دروازے ایک شدت سے برسنے والے پانی کے ذریعہ سے کھول دیئے.غرض آیات قرآنیہ سے ثابت ہے کہ پانی اوپر سے بھی برسا اور زمین سے بھی نکلا اور دونوں پانیوں کے ملنے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر تباہی آئی اور یہ بات نہ صرف یہ کہ خدا تعالیٰ کی قدرت میں ہے بلکہ اس کے عام قانون قدرت کے بھی مطابق ہے.یہ عام قاعدہ ہے کہ جب بارش زور سے پڑے تو زمین سے بھی پانی ابلنے لگ جاتا ہے اور خصوصاً پہاڑی علاقوں میں کہ جہاں چشموں کا پانی اونچے پہاڑوں پر پڑی ہوئی برف کے پانی سے نکلتا ہے جس وقت بارش ہوتی ہے تو برف کے گھلنے کی وجہ سے ان کے پانیوں میں زیادتی آجاتی ہے.
Page 272
حضرت نوح ؑپہاڑی علاقہ میں رہتے تھے اور یہ بات قرآن کریم اور تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت نوح ؑ پہاڑی علاقہ میں رہتے تھے کیونکہ اس آیت سے آگے دو آیتیں چھوڑ کر تیسری آیت میں حضرت نوح ؑ کے بیٹے کا قول نقل کیا ہے کہ سَاٰوِیْ اِلٰی جَبَل میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا.جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ علاقہ پہاڑی تھا اور حضرت نوح ؑ پہاڑوں کے درمیان کسی وادی میں رہا کرتے تھے.ورنہ یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ طوفان کے آنے پر ان کے بیٹے نے کہا ہو کہ میں دوڑ کر سو یادوسو میل کے کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا.اس کا فقرہ صاف بتاتا ہے کہ وہ بالکل دامن کوہ میں کھڑا ہوا تھا اور باوجود اس کے کہ طوفان بڑھ رہا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں آسانی سے پہاڑ پر چڑھ کر بچ سکوں گا.لفظ کل سے مراد مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ میں کل سے مراد صرف وہی جانور ہیں جوحضرت نوح ؑ کے گھر میں موجود تھے.اور عموماً کل انہی افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو عرف عام کے مطابق اس کے نیچے آسکیں نہ کہ کل افراد پر.قرآن کریم میں ملکہ سبا کی نسبت آتا ہے اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (النمل:۲۴) اسے ہر ایک شے دی گئی تھی مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پیغامبروں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے ملکہ تیری ہستی ہی کیا ہے میں تجھے ہلاک کردوں گا.اگر کل کے معنی سب کچھ کے ہی ہوتے تو ضروری تھا کہ جو کچھ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا وہ بھی اس کے پاس ہوتا.لیکن اس جگہ کل کے معنی کوئی شخص سب کچھ نہیں کرتا بلکہ مفسرین بھی یہی معنی کرتے ہیں کہ سب قسم کی ضرورتوں کے سامان اس کے پاس تھے(روح المعانی زیر آیت ھٰذا).پس کوئی وجہ نہیں کہ یہی معنی یہاں نہ کئے جائیں اور یہ نہ کہا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی انہی جانوروں کے جوڑے لینے کا حکم دیا گیا تھا جن کی انہیں ضرورت ہو سکتی تھی اور یہی معقول معنی ہیں ورنہ ماننا پڑے گا کہ کروڑوں اربوں حشرات الارض اور درندے سب حضرت نوح ؑ کی کشتی میں جمع ہو گئے تھے.اس صورت میں تو کشتی کوئی چوتھائی حصۂ زمین کے برابر چاہیے.زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ میں تقلیل کی ہدایت یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اس جگہ زوجین کہہ کر تقلیل پر زور دیا ہے کہ جوڑوں سے زائد نہ لو پس یہ زور دینا بھی بتارہا ہے کہ حکم صرف ضروری اشیاء کے لئے تھا نہ کہ دنیا جہان کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے متعلق.اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ کے معنی اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ کے یہ معنی نہیں کہ سوائے اس کے جس کے متعلق تجھے بتا دیا گیا ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ سوائے اس کے کہ جس کے خلاف الٰہی فیصلہ ہوچکا ہے.حضرت نوح علیہ السلام نے اس فقرہ کی نسبت یہ خیال کیا کہ یہ صرف استغناء کے اظہار کے لئے ہے جیسے کہ حضرت شعیبؑ نے اپنے مخالفوں سے کہا تھا کہ مَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا.(الاعراف:۹۰) یعنی ہم تمہارے
Page 273
دین میں کسی صورت میں واپس نہیں آسکتے.سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ چاہے کہ ہم ایسا کریں.اب یہ امر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ ایسا کبھی پسند نہیں کرسکتا کہ اپنے نبی کو شرک کی تعلیم دے یا یہ کہ نبی مرتد ہوجائے.پس اس جگہ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ سے درحقیقت اللہ تعالیٰ کا استغناء ظاہر کرنا مقصود ہے اور نیز یہ بتانا کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو محدود نہیں کیا جاسکتا.نہ یہ بتانا کہ بالکل ممکن ہے کہ نبی بھی مرتد ہو جائے.وَ قَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖؔىهَا وَ مُرْسٰىهَا١ؕ اِنَّ اور (جب طوفان آگیا تو ہمارے حکم سے) اس نے (اپنےساتھیوں کو) کہا (کہ) اس میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰۰۴۲ اس کا ٹھہرایاجانااللہ (تعالیٰ) کے نام کی( برکت) سے ہی ہو گا.میرا رب یقیناً یقیناً بہت ہی بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.مَجْرٖی اصل میں مَجْرٰی ہے جس کے معنی چلنے کے ہیں اور یہ لفظ جَرٰی یَجْرِیْ کا مصدر میمی ہے اور اسم ظرف بھی ہوسکتا ہے اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے چلنے کا وقت یا جگہ.مُرْسٰی.مُرْسٰی اَرْسٰی میں سے نکلا ہے اَرْسٰی کے معنی ہیں ٹھہرایا.اور یہ مصدر میمی ہے جس کے معنی ٹھہرانے کے ہیں اس کا مجرد رَسَا ہے.یہ لفظ کشتی کے لنگر ڈالنے کے متعلق خصوصیت سے استعمال ہوتا ہے.بعض قرائتوں میں مُـجْرِیْھَا وَمُرْسِیْھْا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو اس کا چلانے والا اور ٹھہرانے والا ہے.(تفسیر کبیر لامام الرازی زیر آیت ھٰذا) وَ هِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ١۫ وَ نَادٰى نُوْحُ اوروہ ایک پہاڑوں کی طرح کی (اونچی) موج میں انہیں لئے جا رہی تھی اور(اسی اثناء میں) نوح نے اپنے بیٹے کو ا۟بْنَهٗ وَ كَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَ لَا تَكُنْ مَّعَ در انحالیکہ وہ (اس سے علیحدہ) ایک اور جانب میں تھا.پکارا( کہ) اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار
Page 274
الْكٰفِرِيْنَ۰۰۴۳ ہو جااور کافروں کے ساتھ نہ ہو.حلّ لُغَات.مَعْزِلٌ.عَزَلَ سے نکلا ہے کہتے ہیں عَزَلَ الشَّیْءَ عَنْ غَیْرِہِ یَعْزِلُ عَزْلًا فَعَزَلَ اَیْ نَحَّاہُ عَنْہُ جَانِبًا فَتَنَحّٰی اَیْ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ اسے کسی دوسری چیز سے ایک طرف ہٹا دیا اور وہ ہٹ گیا.گویا لازم و متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے.عَزَلَ فُلَانًا عَنْ مَنْصَبِہٖ اَوْنَحْوِہِ رَفَعَہٗ عَنْہُ اس کام سے اسے ہٹا دیا اَلْمَعْزِلُ اَلْجَانِبُ یُقَالُ ھُوَعَنِ الْحَقِّ بِمَعْزِلٍ أَیْ مَجَانِبٌ لَہٗ مَعْزِل کے معنی ایک طرف کے ہوتے ہیں جب کسی کے متعلق کہتے ہیں کہ ھُوَ عَنِ الْحَقِّ بِمَعْزِلٍ تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص حق سے ایک طرف ہو گیا ہے.(اقرب) تفسیر.ابن نوح کیا ان کا حقیقی بیٹا نہیں تھا مفسرین نے اس بیٹے کے متعلق اختلاف کیا ہے.بعض کے نزدیک یہ حقیقی بیٹا نہ تھا بلکہ رشتہ دار تھا.بعض کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا بیٹا تھا.آپ کی نسل سے نہ تھا.مگر ابن مسعود، ابن عباس، عکرمہ رضی اللہ عنہم، الضحاک، ابن جبیر وغیرہم اور اکثر مفسرین کی رائے میں ان کا بیٹا ہی تھا(البحر المحیط لابن حیّان زیر آیت ھٰذا).میرے نزدیک اس بحث میں پڑنا بے فائدہ ہے جب قرآن کریم اسے بیٹا کہتا ہے اور نوح ؑ کی زبان سے بیٹا کہلواتا ہے اور کوئی دوسری آیت اس کے خلاف نہیں تو وہ ضرور ایسا رشتہ دار تھا جس کے لئے بیٹے کا لفظ بولا جاتا ہے.مسیحی مصنفین کا اس واقعہ کے بیان پر اعتراض مسیحی مفسرین اس بیٹے کے واقعہ پر معترض ہیں کہ یہ بائیبل کے خلاف ہے مگر بائیبل ایسے ناقص حالات میں ہے کہ اس کی بناء پر قرآن کریم پر اعتراض کرنا حیرت انگیز ہے.(تفسیر ویری زیر آیت ھٰذا) قَالَ سَاٰوِيْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَآءِ١ؕ قَالَ لَا اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر جا ٹھہروں گا (اور) پناہ لوں گا( جو) اس پانی سے مجھے بچا لے گا.اس نے کہا( کہ) عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ١ۚ وَ حَالَ اللہ (تعالیٰ) کے (اس عذاب کے )حکم سے آج کوئی بھی (کسی کو) بچانے والا نہیں (ہو سکتا) سوائے اس کے جس
Page 275
بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ۰۰۴۴ پر وہ(آپ) رحم کردے اور( اسی اثناء میں) پانی کی لہر ان (دونوں) کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق کئے جانے والوں میں (شامل) ہو گیا.حلّ لُغَات.اَوٰی.اَوٰی مَنْزِلَہٗ اَوْاِلٰی مَنْزِلِہٖ نَزَلَ بِہٖ لَیْلًا اَوْنَہَارًا.(اقرب) دن کو یا رات کو اپنے گھر میں آ ٹھہرا.یعنی اَوٰی کے معنی ہیں بے اطمینانی کی جگہ سے آرام کی جگہ پر آ گیا.عَصَمَ.عَصَمَ یَعْصِمُ عَصْمًا.اَلشَّیْءَ مَنَعَہٗ اسے رو ک دیا.اَللہُ فُلَانًا مِنَ الْمَکْرُوْہِ حَفِظَہٗ وَوَقَاہُ خدا تعالیٰ نے فلاں شخص کو تکلیف سے محفوظ رکھا اور بچا لیا.(اقرب) تفسیر.حضرت نوح کا مقام رہائش پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح ؑ کی رہائش کا مقام پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا کیونکہ تبھی تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا.کسی کا لفظ علاقہ کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی کثرت پر دلالت کرتا ہے.معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک وادی تھی اور ایسی جگہ پر پانی کایکدم اونچا ہوجانا اور غیر معمولی طور پر بلند ہوجانا خلاف عقل نہیں ہے.اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نادان انسان آخر تک واقعات سے آنکھیں بند کئے بیٹھا رہتا ہے.طوفان آرہا ہے لیکن باوجود اس کے حضرت نوح ؑ کا بیٹا اپنے باپ کے پیغام میں شک کررہا ہے.اِلَّا مَنْ رَّحِمَ کے معنی اِلَّا مَنْ رَّحِمَ استثناء مفرغ ہے.اور اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا آج کوئی بچانے والا نہیں.ہاں مگر وہ شخص محفوظ رہے گا جسے خدا تعالیٰ بچائے.حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح ؑ کو بیٹے کے غرق ہونے کا نظارہ دیکھنے سے بچا لیا اور ایک بلند موج کے پردہ میں اسے غرق کیا.وَ قِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَ يٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَ غِيْضَ اور( زمین سے بھی) کہہ دیا گیا (کہ) اے زمین تو( اب) اپنے پانی کو نگل جا اور(آسمان سے بھی کہ) اے آسمان الْمَآءُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ (اب) تو (برسنے سے) رک جااور پانی کو جذب کر دیا گیا اور (یہ) معاملہ ختم کر دیا گیا اور وہ( کشتی) جو دی پر
Page 276
بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۰۰۴۵ (جاکر)ٹھہرگئی اور کہہ دیا گیا( کہ) ان ظالم لوگوں کے لئے ہلاکت ہے.حلّ لُغَات.بَلِعَہٗ یَبْلَعُ وَابْتَلَعَہٗ اَ نْزَلَہٗ مِنْ حُلْقُوْمِہٖ اِلٰی جَوْفِہٖ وَلَمْ یَمْضَغْہُ بَلَعَ اور اِبْتَلَعَ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر چبانے کے کسی چیز کو گلے سے پیٹ میں اتار دیا.(اقرب) اَقْلَع عَنِ الْاَمْرِ.کَفَّ.رک گیا.(اقرب) غَاضَ الْمَآءُ.نَقَصَ اَوْغَارَفَذَھَبَ فِی الْاَرْضِ وَغَاضَ الْمَآءُ نَقَصَہٗ.یعنی غاض لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے.اور اس کے معنی زمین میں جذب ہوجانے کے بھی ہوتے ہیں اور کم کردینے کے بھی ہوتے ہیں.(اقرب) اِسْتَوٰی اِسْتَوٰی عَلٰی ظَھْرِ دَآ بَّۃٍ اِسْتَقَرَّ.سواری پر ٹک گیا.(اقرب) بَعُدَ.بَعُدَ یَبْعُدُ بُعْدًا ضِدّ قَرُبَ.یعنی یہ قریب ہونے کے مخالف معنی دیتا ہے وَفُلَانٌ اَیْ مَاتَ.اور جب یہ انسان کے لئے آئے تو کبھی اس کے معنی فوت ہوجانے کے بھی ہوتے ہیں.(اقرب) وَ نَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَ اِنَّ اور نوح نے (اس وقت) اپنے رب کو پکارا اور کہا (اے) میرے رب ! میرا بیٹا یقیناً میرے اہل میں سے ہے اور وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ۰۰۴۶ تیرا وعدہ (بھی) یقیناً نہایت سچاہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوںسے بڑھ کر( بہتر اور درست) فیصلہ کرنے والا ہے.تفسیر.انبیاء کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے کیسا مؤدب ہوتا ہے.کلام الٰہی سے حضرت نوح علیہ السلام کو اجتہادی غلطی لگی.اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ میرے تمام اہل نجات پائیں گے.لیکن جب بیٹا غرق ہونے لگا تو کس لطیف پیرایہ سے خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ خدایا یہ میرے اہل میں سے ہے یعنی میں اس وعدہ کا واسطہ دے کر اس کی نجات کا خواہاں ہوں.مگر چونکہ ظاہری سامان اس کی نجات کے خلاف تھے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ڈوب بھی جائے تو میں یہ خیال نہیں کروں گا کہ تیرا وعدہ جھوٹا تھا تیرا وعدہ بہرحال سچا ہے.اور تیرا فیصلہ بالکل درست ہے.ایسے صدمہ کے وقت میں اس ادب اور اس ایمان کا ظہور صرف اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں سے ہی ممکن ہے.
Page 277
قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ١ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے ہرگزنہیں (اور تمہاری) یہ( دعا) یقیناً ایک (نادرست و )بے محل کام ہے.صَالِحٍ١ۖٞۗ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ١ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ پس جس چیز (کی بھلائی یا برائی) کا تجھے کچھ علم نہیں وہ مجھ سے مت مانگ.میں تجھے نصیحت کر تا ہو ں (تا)کہ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ۰۰۴۷ تو (کہیں )جہالت دکھانے والوں میں سے (نہ) بنے.تفسیر.کوئی غیر مومن حقیقتاًنبی کے اہل خانہ سے نہیں ہو سکتا کیسے مختصر الفاظ میں حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے.کہ جب اہل کہا تھا تو اس سے مراد تمام اہل نہ تھے بلکہ مومن اہل تھے کیونکہ تیرا حقیقی اہل وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو.اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ کے دو معنی اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ کے دو معنی ہوسکتے ہیں.یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ فقرہ حضرت نوح ؑ کی دعا کے متعلق ہو.اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تیرا عمل یعنی دعا بے محل ہے کیونکہ صالح کے معنی مناسب حال کے ہوتے ہیں.مطلب یہ کہ ہم پہلے اس امر کا اعلان کرچکے ہیں اور اب عذاب کا وقت آچکا ہے اب اس دعا کا فائدہ نہیں ہوسکتا.اور یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ یہ جملہ بیٹے کے متعلق ہو اور عمل بمعنی عامل کے ہو.یا ذو کا لفظ محذوف ہو اور یہ دونوں باتیں عربی محاورہ کے مطابق جائز ہیں.اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ یہ لڑکا تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ نامناسب اعمال کرتا رہا ہے.یا یہ کہ اس کے عمل بے محل اور تقویٰ سے دور تھے.عربی زبان کا محاورہ ہے کہ مبالغہ کے لئے مصدر کا صیغہ بجائے اسم فاعل کے استعمال کردیتے ہیں.چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے فَاِنَّـمَا ھِیَ اِقْبَالٌ وَاِدْبَارٌ.وہ (اونٹنی) اپنے بچوں کو کھوبیٹھنے کی وجہ سے ایسی بے قرار ہے کہ گویا آنا اور جانا ہی (بنی ہوئی ) ہے.(لسان العرب زیر مادہ قیل) اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ.یعنی تو تو کلام الٰہی کا حامل ہے تجھے آئندہ چاہیےکہ کلام الٰہی کے سب پہلوؤں پر غور کر لیا کرے.گویا یہ اجمال جو پیشگوئی میں واقع ہوا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لئے ایک ذریعہ عبرت بناتا ہے
Page 278
اور فرماتا ہے کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کرو.اور یاد رکھو کہ پیشگوئیاں کئی معنی رکھتی ہیں اور اصل حقیقت ان کی پورا ہونے پر ہی ظاہر ہوتی ہے.خدا تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنی چاہیے نہ کہ کوئی ایسی چیز جس کے نیک و بد کا کچھ علم نہ ہو فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌکے دو معنی ہوسکتے ہیں.ایک یہ کہ ایسے امر کے متعلق دعا نہ کر جس کا تجھے علم نہ ہو اور یہ بھی ایک اہم بات ہے جس کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں.انسان عالم الغیب نہیں اسے معلوم نہیں ہوسکتا کہ جس چیز کو وہ مانگتا ہے وہ اس کے لئے کیسی ہوگی.مبارک یا منحوس.پس دعا کرتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیےکہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اگر یہ چیز اچھی ہو تو مجھے ملے ورنہ نہیں.دعائےاستخارہ اور اس کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکتہ پر خود بھی عمل کیا ہے اور دوسروں سے بھی عمل کرایا ہے.آپ ہر نئے کام سے پہلے یہ دعا مانگنے کا حکم دیتے ہیں.اَللّٰہُمَّ اِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ ھٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌلِیْ فِی دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَۃِ اَمْرِیْ فَاقْدُرْہُ لِیْ وَیَسِّرْہُ لِی ثُمَّ بَارِکْ لِیْ فِیْہِ وَاِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ ھٰذَا الْاَمَر شَرٌّلِّیْ فِی دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَۃِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْہُ عَنِّی وَاصْرِفْنِیْ عَنْہُ وَاقْدُرْلِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ کَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ (بخاری کتاب التہجد باب ما جاء فی التطوع مثنٰی مثنٰی).یعنی اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات میرے لئے اچھی ہے میرے دین اور میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے تو یہ مجھے حاصل ہوجائے اور آسانی سے حاصل ہوجائے اور اس میں میرے لئے برکت ڈال دے.اور اگر تیرے علم میں یہ بات میرے دین اور میری دنیا کے لحاظ سے اور میرے انجام کے لحاظ سے بری ہے تو تو اسے مجھ سے دور کردے اور میرے دل کو اس سے پھیر دے اور جو چیز میرے لئے اچھی ہو جہاں بھی ہو میرے لئے مہیا کردے اور مجھے بھی اس کے متعلق شرح صدر عطا فرمادے.کیسی مکمل دعا ہے اور کس طرح اس اصل کی اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ انسان جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہو بلکہ ممکن ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں جو عالم الغیب ہے وہ بات انجام کو مدنظر رکھتے ہوئے بری ہو.پس اس سے یہ نہیں کہنا چاہیےکہ وہ بات ہو اور وہ نہ ہو بلکہ یہ کہنا چاہیےکہ اگر اس کا انجام اچھا ہو تو پھر مجھے ملے ورنہ میرے دل سے اس کی خواہش نکال دے.ہاں جن باتوں کا انسان کو علم ہو کہ وہ ضرور اچھی ہیں ان کے متعلق وہ دعا کرسکتا ہے کہ وہ اسے مل جائیں.مثلاً ہدایت یا رضائے الٰہی یا لقائے الٰہی کی اگر انسان دعا کرے یا یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی خیر عطا کرے تو ایسی دعائیں جائز ہیں.احتیاط ایسے امور کے متعلق کرنی چاہیےجن کا انجام معلوم نہیں اور حضرت نوح ؑ کا بیٹے کے لئے اشارتاً دعا کرنا کہ وہ کشتی میں چڑھ جائے
Page 279
ایسے ہی امور میں سے تھا جن کا انجام معلوم نہیں تھا.بالکل ممکن تھا بلکہ غالباً یہی واقع تھا کہ اگر وہ بچ جاتا تو اس کے ذریعہ سے دین کو نقصان پہنچتا اور وہ مذہب کو طاقت پہنچانے کی بجائے اس کی کمزوری کا موجب ہوجاتا.پس اس کا فنا ہونا ہی بہتر اور مناسب تھا.سوال صرف ایسے کرنے چاہئیں جو زیادۃِعلم کا موجب ہوں اور اگر سوال کے معنی دعا مانگنے کی جگہ دریافت کرنے کے کئے جائیں تو اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ سوال صرف ایسے امور کے متعلق کرنا چاہیےجن کے جواب سے علم میں زیادتی ہو.اور انسان کے لئے اس کی حقیقت کو سمجھنا ممکن ہو.مگر وہ باریک حکمتیں جن پر قانون قدرت کا مدار ہے اور جو صرف ایک دو واقعات پر مبنی نہیں ہوتیں بلکہ لاکھوں کروڑوں امور جن میں سے بعض لاکھوں سال پہلے کے ہوتے ہیں اور بعض آئندہ ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں ان پر ان کی بنیاد ہوتی ہے ان کے متعلق سوال فضول ہے کیونکہ ان کا پورے طور پر سمجھنا انسانی طاقت سے بالا ہوتا ہے کیونکہ ان کے سمجھنے کی انسان کو قابلیت ہی نہیں دی گئی.مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ سے مراد اس صورت میںیہی ہے کہ جن کے سمجھنے کی تجھے طاقت نہیں دی گئی ان کے متعلق سوال نہ کر یا یہ کہ جن امور کو تیرے دائرہ علم سے باہر رکھا گیا ہے ان کے متعلق سوال نہ کر.عدم علم اس جگہ مراد نہیں کیونکہ سوال تو کیا ہی اس وقت جاتا ہے کہ جب انسان کو علم نہ ہو.جس امر کا علم ہو اس کے متعلق اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی.پس علم نہ ہونے سے مراد اس جگہ علم کے احاطہ سے باہر ہونے کے ہیں اور اس میں کیا شک ہے کہ جن امور کی حقیقت کو انسان نہ سمجھ سکتا ہو یا جن کی تفصیل کا اظہار نامناسب ہو ان کے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیے.حضرت نوح اپنے بیٹے کے اعمال سے بے خبر تھے اللہ تعالیٰ کے اس جواب سے کہ ان کے بیٹے کے اعمال اچھے نہ تھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر سے اس کے اعمال پوشیدہ تھے.اس سوال سے حضرت نوح کوکیوں روکا گیا اور نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح ؑ کو جو سوال سے روکا گیا ہے تو اسی وجہ سے کہ اس طرح ان کے بیٹے کی پردہ دری ہوتی تھی اگر ان کے سوال کا صحیح جواب دیا جاتا تو تفصیلاً اس کے عیوب بیان کرنے پڑتے جو اللہ تعالیٰ کی ستاری کے خلاف تھا اس لئے ایک مختصر جواب دیا کہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے اور مزید سوالات سے روک دیا تاکہ اور زیادہ غیب سے پردہ نہ اٹھانا پڑے.اس امر سے اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کی ستاری کا ایک نہایت دلکش جلوہ نظر آتا ہے.ایک طرف غرق کا حکم ہے.دوسری طرف پردہ پوشی بھی ہورہی ہے.ان معنوں کے رو سے ’’جاہل نہ بن‘‘ کے یہ معنی ہوں گے کہ ایسے امور کو خود ہی سمجھ لینا
Page 280
چاہیےاور سوال نہیں کرنا چاہیے اور اس میں کیا شک ہے کہ بعض امور کے متعلق سوال کرنا مشکلات پیدا کردیتا ہے.ان کے متعلق خود ہی اجتہاد کرلینا سوال کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے.اس جگہ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وعدہ تو خدا تعالیٰ کا کوئی بیان نہیں ہوا بلکہ الہام الٰہی میں صرف حکم بیان ہوا ہے کہ فلاں قسم کے لوگوں کو کشتی میں بٹھالے.اب اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا تو وہ نافرمان بن گیا.خدا تعالیٰ پر وعدہ خلافی کا الزام کس طرح لگ سکتا تھا.اور جب خدا تعالیٰ پر وعدہ خلافی کا کوئی الزام نہیں لگ سکتا تھا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول کا کیا مطلب ہوا کہ اِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ.سو اس کا جواب یہ ہے کہ وعدہ ضرور تھا گو جو الفاظ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں وہ حکم کے رنگ میں ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ بعض دفعہ حکم بھی وعدہ کا رنگ رکھتا ہے.جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں کو کشتی میں بٹھالیجئیو تو اس کے یہ معنی تھے کہ میں ان کو بچاؤں گا.اور یہ امر کہ یہ وعدہ تھا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں ایک استثناء فرمایا ہے کہ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ (ہود:۴۱) لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ جن کے متعلق فیصلہ ہوچکا ہے کون لوگ ہیں.اب اگر اس عبارت میں حکم ہوتا وعدہ نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا جاتا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے متعلق فیصلہ ہوچکا ہے.تاکہ حضرت نوح ؑ ان کو کشتی میں نہ بٹھائیں.مگر انہیں ان کے ناموں یا ان کے افعال سے بالکل واقف نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہوئی کہ حضرت نوح ؑ کے بیٹے نے جب کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو تعجب ہوا.پس جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام جن کو نہیں بٹھانا تھا ظاہر نہیں کئے تو صاف ظاہر ہے کہ حکم کے الفاظ میں یہ ایک وعدہ تھا اور چونکہ اس کا ایفاء اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا اس لئے ان لوگوں کے نام جو اس وعدہ سے مستثنیٰ تھے اس نے ظاہر کرنے پسند نہ کئے.دوسری دلیل وعدہ کی موجودگی کی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں نے کب کسی کے بچانے کا وعدہ کیا تھا.میں نے تو صرف حکم دیا تھا کہ گھر کے لوگوں اور مومنوں کو کشتی میں بٹھا لیجیئو.اب اگر ان میں سے کوئی کشتی میں نہیں بیٹھا تو یہ اس کا قصور ہے بلکہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے اس سوال کو کہ تیرا وعدہ تو اہل کے بچانے کا تھا قبول کرلیتا ہے اور یہ جواب دیتا ہے کہ وعدہ اہل کے متعلق تھا اور یہ لڑکا حقیقتاً تیرا اہل نہیں ہے.اس امر پر روشنی ڈالنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی ہے کہ بعض نادان لوگ پیشگوئیوں کے سمجھنے میں اجتہادی غلطی کے لگنے کے منکر ہیں اور جب انہیں قرآن کریم کی یہ آیات بتلائی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ
Page 281
کوئی وعدہ نہ تھا بلکہ ایک حکم تھا لیکن جیسا کہ اوپر ثابت کیا جاچکا ہے حضرت نوح ؑ سے اہل کے متعلق ایک وعدہ تھا لیکن اس کے صحیح معنی وقت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نہیں سمجھے اور انہیں اجتہادی غلطی لگ گئی.وقت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا.قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ (نوح نے) کہا ( اے) میرے رب! میں اس بات سے تیری پناہ چا ہتا ہوں کہ میں تجھ سے (آئندہ) کوئی ایسی عِلْمٌ١ؕ وَ اِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَ تَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ۰۰۴۸ چیز مانگو ں جس (کی بھلائی یا برائی) کا مجھے کچھ علم نہ ہو اور اگر تو( میری یہ غلطی) مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ ں گا.تفسیر.نوح ؑ کا نہ صرف اپنی غلطی سے رجوع بلکہ آئندہ کے لئے خدا کی پناہ چاہنا انبیاء کیسے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سن کر انہوں نے اپنے قول سے خالی رجوع ہی نہیں کیا.بلکہ یہ بھی دعا کی ہے کہ گو میں آئندہ ایسی غلطی کے ارتکاب سے بچنے کی کوشش کروں گا لیکن تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوسکتا.اس لئے تو بھی میری مدد کر.کہ میں آئندہ ایسا کوئی فعل نہ کروں.کیسے نادان لوگ ہیں وہ جو بہت ادنیٰ مقام کے ہوکر بھی بڑے بڑے دعوے کردیتے ہیں اور انبیاء کے طریق عمل سے نصیحت حاصل نہیں کرتے.نبیوں کی استغفار کی حقیقت اس آیت سے نبیوں کے استغفار کی بھی حقیقت کھل جاتی ہے اس جگہ حضرت نوح ؑ کا استغفار بیان ہوا ہے لیکن جیسا کہ اوپر کی آیات سے ظاہر ہوا ہے ان سے صرف اجتہادی غلطی ہوئی تھی جو شریعت کا گناہ نہیں بلکہ بشری کمزوری ہے باوجود اس کے وہ استغفار کرتے ہیں.پس معلوم ہوا کہ استغفار سے گناہ کا ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ لفظ بشری کمزوریوں کے نتائج سے بچنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.
Page 282
قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَ بَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَ عَلٰۤى (اس پر اسے) کہا گیا (کہ) اے نوح ! تو ہماری طرف سے (عطا شدہ) سلامتی اور (طرح طرح کی) برکات کے اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ١ؕ وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا ساتھ جو تجھ پر اور جو( لوگ) کہ تیرے ساتھ ہیں ان میں سے کئی جماعتوں پر (نازل کی جاتی) ہیں اتر جا.اور بعض عَذَابٌ اَلِيْمٌ۰۰۴۹ جماعتیں( ایسی بھی) ہیں جنہیں ہم ضرور( دنیا کا عارضی) سامان عطا کریں گے( مگر) پھر ان پر ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا.حلّ لُغَات.بَرَکَاتٌ.بَرَکَاتٌ بَرَکَۃٌ کی جمع ہے.اَلْبَرَکَۃُ.اَلنَّـمَاءُ نشوونما پانا ترقی کرنا اَلزِّیَادَۃُ.بڑھنا، زیادہ ہوجانا.اَلسَّعَادَۃُ اقبال مند ہونا.خوش نصیب اور خوش حال ہونا.ہر قسم کی نحوستوں اور کدورتوں سے پاک ہونا.بَرَکَ کُلُّ شَیْءٍ بِالْمَکَانِ ثَبَتَ.برک کے معنی ہیں قرار پذیر ہوا.قائم ہو گیا.اور بَارَکَ اللہُ فِیْکَ کے معنی ہیں طَھَّرَ.پاک کیا.ا ور بَارَکَہٗ کے معنی ہیں رَضِیَ عَنْہُ.اس پر راضی ہوا.(اَللّٰہُمَّ) بَارِکْ عَلَی الْاَنْبِیَآءِ وَاٰلِہِمْ أَیْ اٰدِم لَہُمْ مَااَعْطَیْتَہُمْ مِنَ التَّشْرِیْفِ وَالْکَرَامَۃِ اور جب اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو اور مفعول بصلہ عَلٰی ہو تو اس کے معنی شرف و عزت عطا کرنے اور اسے قائم رکھنے کے ہوتے ہیں.(اقرب) تفسیر.موجودہ سب نسل حضرت نوح سے نہیں چلی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دوسرے مومنوں کی بھی نسل چلی اور ان کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے برکات کے وعدے تھے.اور یہ خیال جو لوگوں میں رائج ہے کہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں درست نہیں ہے.بائیبل کے بیان پر قرآن کریم کے اس بیان کو کس قدر فوقیت حاصل ہے.آج ہر ایک تعلیم یافتہ مسیحی دل میں یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیا پر بسنے والے بنی نوع انسان صرف نوح علیہ السلام کی ہی اولاد نہیں ہیں لیکن وہ اس یقین کے وقت بائیبل کا مکذب ہوتا ہے اور قرآن کریم کا مصدق.کیونکہ بائیبل کہتی ہے کہ صرف نوح اور ان کی اولاد اس طوفان سے بچے.اور اسی کی نسل آئندہ دنیا میں پھیلی.(پیدائش باب۷) چنانچہ وہ کل بنی آدم کو تین ہی نسلوں میں
Page 283
تقسیم کرتے ہیں.یعنی سام حام اور یافث کی اولاد جو تینوں حضرت نوح ؑ کے بیٹے تھے.قرآن کریم بتاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کا تو کیا ذکر ہے خود حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی نسلیں بھی چلیں.اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ سے کون لوگ مراد ہیں وَ اُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ.سے یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ حضرت نوح ؑ کے وقت میں بھی اور اقوام تھیں جو ہلاک نہیں کی گئیں بلکہ انہیں ڈھیل دی گئی.اور وہ بعد میں اپنے وقت مقررہ پر ہلاک ہوئیں اور یہ بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اس میں اگلی نسلوں کا ذکر ہے کہ ان سلامتی اور برکت پانے والے لوگوں میں سے ایک گروہ بعد میں بگڑ کر سزا پائے گا.تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ١ۚ مَا كُنْتَ یہ (انذاری بیان) غیب کی (اہم) خبروں میں سے ہے جنہیں ہم تجھ پر وحی (کے ذریعہ سےنازل) کرتے ہیں تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا١ۛؕ فَاصْبِرْ١ۛؕ اِنَّ نہ تو ان کو اس سے پہلے جانتا تھا اور نہ تیری قوم (جانتی تھی).پس تو صبر سے کام لے (اچھا) انجام یقیناً الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَؒ۰۰۵۰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کا (ہی ہوتا) ہے.تفسیر.یہ ذکر دراصل نوح ؑکے واقعہ کا نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے مستقبل کا ہے اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم قصے بیان نہیں کرتا.کیونکہ یہاں فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں یعنی آئندہ ہونے والے واقعات ہیں.بے شک ظاہری طور پر تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے مگر مطلب یہ ہے کہ نوح ؑ کے مشابہ واقعہ تیرے ساتھ بھی گزرے گا.اسی وجہ سے آیت کے آخر میں فرمایا کہ تو بھی صبر سے کام لے.انجام متقیوں کا ہی نیک ہوتا ہے.یعنی جس طرح نوح ؑ کی قوم تباہ ہوئی تیری قوم کا ایک حصہ بھی تباہ ہوگا.اور خدا تعالیٰ تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایک نئی نسل چلائے گا.جو ہر نئے زمانہ میں نیکی اور تقویٰ کے جھنڈے کے علم بردار رہیں گے.قرآن کریم گذشتہ قصے بیان نہیں کرتا تعجب ہے کہ اس قسم کی آیات کی موجودگی میں بھی بعض لوگ یہ خیال
Page 284
کرتے ہیں کہ قرآن کریم پچھلی اقوام کے قصص بیان کرتا ہے.قرآن کریم تو جو تاریخی واقعہ بھی بیان کرتا ہے وہ صرف یہ خبر دینے کے لئے کرتا ہے کہ آئندہ مسلمانوں سے بھی ایسا ہی ہونے والا ہے چنانچہ ایک بھی تاریخی واقعہ قرآن کریم میں ایسا بیان نہیں ہوا کہ جس کے مشابہ واقعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کے ساتھ نہ گذرا ہو یا جو آئندہ نہ گذرنے والا ہو.اوپر کی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کے متعلق مسلمانوں اور مسیحیوں اور یہودیوں میں بہت کچھ اختلاف ہے.چونکہ کسی ایک آیت کے نیچے اس واقعہ کا ذکر نہیں ہوسکتا تھا اس لئے میں سب آیات کے آخر میں اس کے متعلق اپنی تحقیق اور دوسرے لوگوں کے خیالات لکھ دیتا ہوں.حضرت نوح کے واقعہ پر اجمالی نظر بائیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام لمک کے بیٹے تھے.اور حضرت آدم علیہ السلام سے نویں پشت میں تھے.(حضرت آدم کو شمار کرکے دسویں) جب وہ پانچ سو برس کے ہوئے تو ان کے ہاں سم ،حام اور یافث پیدا ہوئے (پیدائش باب۵ ،۲۸ تا ۳۲) اہل دنیا کی شرارت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا مگر چونکہ نوح ؑ نیک تھا خدا نے اسے پسند کیا اور اسے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور ارشاد کیا کہ علاوہ بیوی بچوں کے کشتی میں طوفان کے وقت حلال جانوروں میں سے سات سات جانور اور دوسرے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا ہر اک قسم کا چڑھا لے (پیدائش باب۶) طوفان کے آنے پر دنیا کے تمام جانور اور انسان ہلاک ہو گئے.مگر نوح ؑ اور ان کے اہل و عیال کشتی کے ذریعے سے بچ گئے اور ان کے اور ساتھ کے جانوروں کے ذریعے سے پھر دنیا آباد ہوئی.اور طوفان کے بعد کشتی اراراٹ پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی.(باب ۷ و ۸) اس کے بعد نوح اور اس کی اولاد سے دنیا پھر بسنے لگی.اور نوح کھیتی باڑی کرنے لگا.ا ور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا.ایک دن اس کی شراب پی کر نشہ میں مست ہو گیا.اس کے بیٹے حام نے سب سے پہلے اسے ننگا دیکھا اور باقی بھائیوں کو بتایا.انہوں نے الٹے پاؤں آکر بغیر دیکھے اس پر کپڑا ڈال دیا.نوح جب ہوش میں آئے تو انہوں نے حام کو بددعا دی اور اس کی اولاد کی نسبت جس نے کنعان کہلانا تھا اور ملک کنعان کو آباد کرنا تھا سام کی غلامی کی پیشگوئی کی اور اسی طرح یہ خبر بھی دی کہ حام کی اولاد یافث کی اولاد کی بھی غلام ہوگی.(پیدائش باب ۹) بائیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح کی اولاد طوفان کے بعد عراق میں آباد ہو ئی بائیبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے بعد نوح کی اولاد عراق موجودہ میں آباد ہوئی.کیونکہ لکھا ہے کہ حام کے پوتے نے بابل وغیرہ پر حکومت کی(پیدائش باب ۱۰).یہودیوں کی احادیث اور روایات کی کتب میں بائیبل سے کسی قدر اختلاف
Page 285
ہے.اس جگہ اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں.نوح کا نام نوح کب رکھا گیا لیکن اس قدر بتا دینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ مدرش اغادہ میں لکھا ہے کہ نوح کا نام اس کے ہل ایجاد کرنے کے سبب سے نوح رکھا گیا تھا(جیوش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Noah).چونکہ بائیبل میں لکھا ہے کہ ان کے والد نے ان کا نام نوح رکھا.اس لئے اس اختلاف کو کتاب سفر ہا یٰشیر میں یوں مٹایا گیا ہے کہ ان کے والد نے ان کا نام مناحیم رکھا تھا.جس کے معنی تسلی دینے والے کے ہیں.طوفان کے بعد ان کا نام نوح ہوا.(جیوش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Noah) حضرت نوح کی نیکی کے متعلق یہودیوں کے مختلف اقوال نوح ؑ کی نیکی کے متعلق بھی اختلاف ہے.بعض انہیں نیک ،بعض معمولی نیک.اور بعض بدکار بھی کہتے ہیں.اور کہتے ہیں کہ وہ محض اپنی نسل میں سے پیدا ہونے والے نیک لوگوں کی خاطر بچایا گیا.حضرت نوح کی شریعت اور کتاب طالمود جو یہودیوں کی کتب احادیث کا مجموعہ ہے اس میں لکھا ہے کہ نوح شریعت والے نبی تھے اور انہوں نے طوفان کے اٹھائیس سال بعد شریعت مرتب کرنی شروع کی.جس میں کچھ تو طبعیات کے مسائل تھے اور کچھ موسیٰ کی شریعت سے ملتے جلتے مسائل تھے.رافائیل فرشتہ نے انہیں علم طب سکھایا تھا.اور بوٹیوں کے خواص سکھائے تھے.اس نے ایک کتاب لکھی جو بعد میں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی.اور یونانیوں اور ہندوستانیوں نے اس کتاب سے علم طب حاصل کیا(جیوش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Noah).(یہودی علماء کو بھول گیا ہے کہ ان کے نزدیک سوائے نوح ؑ کے اور کسی انسان کی نسل دنیا میں باقی نہ رہی تھی اس وجہ سے سب دنیا میں نوح کی ہی اولاد تھی.پھر انہیں کسی ترجمہ سے فائدہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اپنے دادا کے علوم کو اس کی اپنی زبان میں سمجھتے تھے مگر سچ ہے دروغ گو راحافظہ نباشد).طوفان نوح کا تاریخی ثبوت یہ ایک عجیب بات ہے کہ نوح کے واقعہ سے ملتے جلتے واقعات پر مبنی روایات دنیا کے قریباً ہر براعظم میں ملتی ہیں.(دیکھو انسائیکلوپیڈیا ببلیکازیر لفظ Deluge) یونان کی قدیم روایات میں بھی ایک ایسے انسان اور اس کے وقت میں طوفان کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ بھی اس قسم کے کسی تاریخی واقعہ سے واقف تھا.شمالی امریکہ کے قدیم باشندوں کی روایات شمالی امریکہ کے قدیم باشندوں میں بھی ایسی روایات پائی جاتی ہیں.حتیٰ کہ بعض جگہ ناموں کی مشارکت بھی ہے.
Page 286
بائبل کی قدیم روایات بابل کی قدیم روایات میں طوفان کے ہیرو کا نام ہسیس اندرا دیا ہے.اور لکھا ہے کہ وہ دسواں بادشاہ تھا.بائیبل بھی آدم کی نسل سے نوح کو دسواں قرار دیتی ہے(پیدائش باب ۵).شمالی امریکہ کی روایتوں میں اس شخص کا نام کنیان بتایا ہے.جس کے معنی عقلمند کے ہیں.اور یہ نام معنوں کے لحاظ سے ہسیس اندرا کے نام سے جو بابل کی روایتوں میں آتا ہے ملتا ہے.پالینیشیا، ایران، کنعان مصر اور ہندوستان میں بھی اس قسم کی روایات پائی جاتی ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک سخت طوفان آیا تھا.اور ایک خاص نیک بندے کے ذریعہ سے کچھ لوگ ایک کشتی میں بچے تھے.چنانچہ بابل کی روایات اور ہندوستان کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے وقت کی ایک شخص کوقبل از وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی بابل کی روایات میں لکھا ہے کہ خواب کے ذریعہ سے اطلاع ملی اور ہندوستان کی روایات میں لکھا ہے کہ دیوتاؤں نے اسے بتایا.(انسائیکلوپیڈیا ببلیکا زیر لفظ Deluge) بابل کی روایتوں میں اس پہاڑ کو جہاں نوح کی کشتی ٹھہری تھی ارمینیا کا پہاڑ قرار دیا ہے.اسلامی مفسروں نے بھی جودی جو اس پہاڑ کا نام قرآن کریم میں آیا ہے اسے آرمینیا کا پہاڑ قرار دیا ہے(الکشاف و ابن کثیر زیر آیت ھذا ).اس طرح قرآن کریم کی روایت اس امر میں بابل کی روایت سے ملتی ہے اور بابل ہی چونکہ نوح ؑ کی اولاد کے رہنے کا مقام تھا جس پر خود بائیبل بھی گواہ ہے اس لئے وہاں کی روایت کو ایک حد تک ضرور فوقیت دینی پڑے گی.خصوصاً جب کہ بابل والوں کو نوح کے واقعہ سے کوئی خاص فائدہ اٹھانا مقصود نہیں تھا.برخلاف بائیبل کے کہ اس کی روایتوں میں یہ بات مدنظر ہوتی ہے کہ سب دنیا کی تاریخ انہی کے گرد چکر کھاتی رہے.اس طوفان کا ذکر ہندوستان کی قدیم تاریخ میں ہندوستان میں اس طوفان کا ذکر سب سے پہلے ستھاپتھا برہمنا نامی کتاب میں ہے.اس میں لکھا ہے کہ منو پہلا انسان تھا.وہ سورج دیوتا دِوَسْوات کا بیٹا تھا.وہ ایک دفعہ نہا رہا تھا کہ ایک مچھلی اس کے ہاتھ میں آ گئی.مچھلی نے اس وعدہ پر نجات حاصل کی کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اس وقت میں تجھے نجات دوں گی.اور اسے ایک کشتی تیار کرنے کی ہدایت کی.جب طوفان آیا تو مچھلی کشتی کو پہاڑ پر لے گئی.اور وہاں طوفان کے کم ہونے پر منو اترا اور اس نے قربانی کی آخر خدا تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی (بغیر ماں کے) عطا کی اور اس سے (بغیر باپ کے) سب دنیا کی نسل چلی.(شت پتھو برہمن اردو ترجمہ آٹھواں ادھیائے صفحہ ۱۱۲،۱۱۳) دوسری روایت مہابہارت میں ہے.اس میں بتایا گیا ہے کہ منو کے ساتھ سات عقلمند لوگ اور بھی تھے اور لکھا ہے کہ وہ مچھلی برھما یعنی خدا تھی اور اس نے منو کو دیوتا اور انسان بنانے سکھائے تھے.
Page 287
تیسری روایت بھگوتا پرانا میں ہے.اس میں جانوروں کے جوڑے ساتھ لینے کا بھی ذکر ہے.روایات کا اس قدر اتفاق حتیٰ کہ بعض جگہ ناموں کا ملنا جیسے کہ ہندوستان میں اس کا نام منو بتانا اور بائیبل میں نوح اور طالمود میں مناحیم جو منو سے بہت ملتا ہے کیونکہ آخری ی اور میم صرف ادب کے لئے عربی زبان میں لگائے جاتے ہیں.پس صرف مناح رہ جاتا ہے جو منو سے ملتا ہے.اسی طرح بابل کے نام اور امریکہ کی قدیم روایتوں کے ناموں کے معنوں کا ملنا ہر جگہ ایک کشتی کا ذکر ہونا اور طوفان سے صرف چند آدمیوں کے بچ کر نکلنے کا بیان کیا جانا بتاتا ہے کہ یہ واقعہ ایک زبردست تاریخی واقعہ ہے.جس پر دنیا کی سب قومیں شاہد ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا سب دنیا پر اثر پڑا تھا.تبھی تو سب دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر پایا جاتا ہے.طوفان کا یہ ذکر تمثیلی نہیں ہوسکتا چونکہ بظاہر سب دنیا پر ایسے طوفان کا آنا محال نظر آتا ہے اس لئے علوم جدیدہ کے ماہروں نے اس واقعہ کو ایک تشبیہی کہانی قرار دیا ہے.اور یہ معنی کئے ہیں کہ پرانے زمانہ میں ستاروں کی گردش وغیرہ کا ذکر تمثیلی زبان میں بعض لوگوں نے کیا ہے اس سے دھوکہ کھاکر یہ قصہ مشہور ہو گیا ہے(انسائیکلوپیڈیا ببلیکا زیر لفظ Deluge).مگر یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ اس تمثیلی قصہ کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہو گئی ہے.اور سب دنیا کی قوموں کے دلوں پر اس قدر گہرا اثر اس کا کیوں پڑا ہے.اور کیوں دوسرے قصوں کو چھوڑ کر اسے سب دنیا نے یاد رکھا ہے.اور پھر سوال یہ ہے کہ قصہ تو آخر کسی ایک جگہ کے لوگوں نے بنایا ہوگا.وہ اس طرح سب دنیا میں کس طرح پھیل گیا.اور ہر زبان کی مذہبی تاریخوں میں اس کا ذکر ہونے لگا.کون سا عقل مند اس امر کو تسلیم کرسکتا ہے کہ ایک ملک میں بنایا جانے والا قصہ قدیم زمانہ میں جبکہ تعلقات بہت محدود تھے اس طرح مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں پھیل گیا.اور یکساں اہمیت پا گیا اور سب مذاہب کا جزو بن گیا.قرآن کریم سے اس واقعہ کے متعلق کیا ثابت ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس تواتر اور اس عظمت کو دیکھ کر جو اس قصہ کو حاصل ہے اس امر سے انکار نہیں ہوسکتا کہ یہ واقعہ ضرور ہوا ہے.اور اس کا تعلق بھی سب دنیا سے ہے.اور ہوا بھی غیر معمولی طور پر ہے اور جب ہم اس نتیجہ تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ امر ہمارے لئے سمجھنا بالکل آسان ہوجاتا ہے کہ وہ واقعہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے ان سب نتائج کے مطابق پورا اترتا ہے اور اس سے کوئی بات قانون طبعیات کے خلاف بھی نہیں ماننی پڑتی.کیونکہ قرآن کریم سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرانے زمانہ میں ایک زبردست طوفان آیا تھا.جس سے اس ملک کے سب باشندے تباہ ہو گئے تھے.اور یہ کہ اس
Page 288
طوفان کے ہیرو نوح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے خاص برکت دی تھی.اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی نسل کو خاص غلبہ دنیا میں عطا کیا تھا.باقی اور اقوام بھی اس وقت تھیں جو اس عذاب میں شامل نہ تھیں.ایک مدت تک اپنے دن گزار کر وہ اپنے انجام کو پہنچ گئیں.اور یہ بھی ثابت ہے کہ یہ طوفان اس قدر شدید تھا کہ کشتیوں میں پناہ لینی پڑی اور آسمان سے بھی بارش ہوئی اور زمین کے چشمے بھی پھوٹ پڑے اور بعض پہاڑیوں کی چوٹیوں تک پانی پہنچ گیا.یہ طوفان عالمگیر نہیں تھا یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن کا انکار کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہوسکتی.قرآن کریم سے ثابت ہے اور ہر ملک کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملک پہاڑی تھا اور قرآن کریم سے مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی وادی تھی جس کے پاس بہت سے پہاڑ تھے.پس یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وادی کا منہ پہاڑوں کے بالمقابل سلسلوں کی وجہ سے تنگ ہو.جیسا کہ اکثر پہاڑی وادیوں میں ہوتا ہے.زلزلہ کے سبب سے پتھروں کے گرنے سے یا برف کی سلوں کے پھسل کر آپڑنے کے سبب سے اس وادی کا منہ بند ہو گیا ہو.اور اوپر سے تیز بارش کے ہونے اور نیچے سے چشموں کے پھوٹنے کے سبب سے پانی اس قدر جمع ہو گیا ہو کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی کے نیچے آگئی ہوں.جیسا کہ ۱۹۲۸ میں ہی تبت کی پہاڑیوں میں ایک گلیشیر کے گرنے کی وجہ سے حادثہ ہوچکا ہے.چونکہ یہ واقعہ بنی نوع انسان کی تہذیب کے ابتدائی دور میں ہوا ہے اور حضرت نوح ؑ اس دور کے پہلے فرد ہیں جیسا کہ احادیث میں انہیں پہلا رسول کہا گیا ہے اور اسی طرح بائیبل سے بھی ثابت ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ دورتہذیب کے بانی حضرت نوح ؑ ہیں.ہندو روایات بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہیں کیونکہ ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منو پہلا انسان تھا لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ساتھ سات اور آدمی بھی طوفان سے بچے تھے.پس ان دونوں باتوں کو ملاکر یہی ثابت ہوتا ہے کہ منو تہذیب کے دور کا پہلا انسان تھا.ورنہ انسان ہونے کے لحاظ سے وہ پہلا نہ تھا.ان تین اہم بیانات کے اتفاق کے بعد جو مختلف ممالک کے مذاہب کا ہے اس کے ماننے میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ تہذیب اور تمدن کی بنیاد نوح ؑ سے پڑی ہے.اور یہ ایک امر واقع ہے کہ جب کوئی قوم تہذیب اور تمدن میں ترقی کرنے لگتی ہے تو اس کی نسل بھی کثرت سے بڑھنے لگ جاتی ہے.اور اس کے ساتھ بسنے والی دوسری اقوام خودبخود کم ہونے لگ جاتی ہیں.چنانچہ جس جس ملک میں بھی کوئی نسبتاً زیادہ مہذب قوم جاکر بسی ہے اس نے یا تو دوسری اقوام کو جو اس سے تہذیب میں کم تھیں مٹا دیا ہے یا بہت کمزور کر دیا ہے.پس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح کی اولاد او ران کے ہمراہیوں کی اولاد جو تہذیب کے دور کی اول کڑی تھی جن جن ملکوں میں پھیلی ہے
Page 289
اس نے وہاں کی پہلے سے آبادشدہ نسلوں کو یا تو بالکل مٹا دیا یا اپنے اندر جذب کرکے یا ان کی طاقت توڑ کر بالکل کمزور کر دیا.اور اپنی روایات اور اپنے آثار کو ساری دنیا میں پھیلا دیا.اس کی وجہ سے وہ طوفان کا قصہ جس نے یقیناً ان کے دلوں پر ایک گہرا اثر ڈال دیا ہوگا.ان کے ساتھ ساتھ ہی سب دنیا میں پھیلتا گیا.طوفان کا واقعہ ایک ہی ہے نہ مختلف ملکوں کے مختلف واقعات پس نہ یہ درست ہے کہ نوح کا طوفان سب دنیا پر آیا اور نہ یہ درست ہے کہ یہ سب قصص جو مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں مختلف واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں.واقعہ ایک ہی ہے اور طوفان بھی ایک ہی ملک میں آیا ہے لیکن چونکہ نوح ؑ دور تہذیب کے انسان اول ہیں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی اولاد طوفان کے بعد مختلف ممالک میں پھیل گئی اور اپنی اعلیٰ تہذیب اور بہتر تمدن کی وجہ سے اصلی باشندوں پر غالب آکر یا تو وہی باقی رہ گئی یا پھر ان کو اس نے ایسا مرعوب کرلیا کہ انہوں نے بھی نوح ؑ کی امت کی تہذیب کو اختیار کرلیا.اور اس طرح دنیا کے ہر ملک میں طوفان نوح کا قصہ پہنچ گیا.اور ایک لمبا زمانہ گذرنے پر جب باہر سے آنے والوں کو اپنے اصلی وطن سے کوئی تعلق نہ رہا تو ہر اک ملک کے شہروں ناموں اور مقام نے اس قصہ میں جگہ لے لی اور اس طرح یہ واقعہ مختلف واقعات کا رنگ اختیار کر گیا.وَ اِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا١ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا اور عاد کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی ہود کو (رسول بنا کر بھیجا )اس نے (یہ حکم پا کر انہیں) کہا اے میری قوم تم لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ١ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ۰۰۵۱ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے.(اس کے شریک مقرر کرنے میں) تم محض افترا ء کرنے والے ہو.تفسیر.شرک کا عقیدہ محض افتراء ہے یعنی واقعات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے اور شرک کا عقیدہ محض ایک افتراء ہے.مطلب یہ کہ شرک کی تائید میں کوئی کمزور سے کمزور دلیل بھی نہیں جس سے یہ خیال بھی کیا جائے کہ اس عقیدہ کے پابند کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں.وہ صرف اپنے آبائی خیالات کی اندھادھند پیروی کررہے ہیں.کیا قوم عاد کوئی تھی ہی نہیں عاد کے متعلق یورپین محققین کا خیال ہے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا.وہ کہتے
Page 290
ہیں کہ جو کتبے عرب سے نکلے ہیں ان سے کسی گذشتہ قوم کا نام عاد نہیں ملتا.صرف اتنا پتہ لگتا ہے کہ سموری قوم سب سے قدیم ہے.ان کی حکومت سب سے پہلی تھی.پھر سامی قوم ہوئی.جن میں حمورابی سب سے مشہور آدمی گذرا ہے.جس کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی تھا.یہ مسیح ؑ سے دوہزار سال قبل اور حضرت موسیٰ سے چھ سو سال قبل تھا.بائیبل سے اس کی تعلیم اس قدر ملتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بائیبل کی تعلیم اس سے چرائی گئی ہے.(ان مسیحیوں کو غور کرنا چاہیےجو قرآن کریم کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم پہلے صحیفوں سے چرائی گئی ہے).ایک قوم کے متعدد نام بھی ہو سکتے ہیں محققین یورپ کا خیال ہے کہ عربوں کے عام قصے سن کر قرآن شریف نے یہ قصہ نقل کردیا ہے میرے نزدیک بنی نوع انسان کی جماعتوں کے نام دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک قومی نام ہوتا ہے اور ایک نسلی نام ہوتا ہے.جیسے کہ آرین ایک اجتماعی اور مشترک نام ہے جس کے ماتحت کئی خاندان ہیں.اب اگر کوئی کہے کہ کتبوں میں سے کوئی گپتا کا کتبہ نکلتا ہے اور کوئی کسی اور کا لیکن آرین کہیں بھی نہیں نکلتا تو یہ اس کی بیوقوفی ہوگی.عاد چند قبائل کا اجتماعی مشترک نام ہے غرض میرے نزدیک عاد ایک مجموعۂ قبائل کا نام ہے اور اس کے ماتحت قبائل میں سے مختلف زمانوں میں بعض قبائل غلبہ اور حکومت حاصل کرتے رہے ہیں.جو اپنے اپنے ناموں کے کتبے نصب کرتے رہے ہیں.مگر وہ سب عاد ہی تھے.قرآن کریم سے اس قدر پتہ لگتا ہے کہ ثمود سے پہلے عاد تھے.پس گو مجموعی نام کا پتہ نہیں ملتا لیکن ہم قیاس کرسکتے ہیں کہ جو قومیں ثمود سے پہلے آباد تھیں ان کامجموعی نام عاد تھا اور اس بات کا ثبوت کہ عاد کا لفظ موجود تھا جغرافیوں سے ملتا ہے.یونان میں جو جغرافیے لکھے گئے ہیں ان میں ایک قبیلے کا نام عاد پایا جاتا ہے.ان میں لکھا ہے کہ یمن میں مسیح کے زمانے سے پہلے ایک قبیلہ حاکم تھا.جس کا نام ADRAMITAI تھا(ارض القرآن جلد ۱ صفحہ ۱۸۳).یہ وہی ہے جو قرآن کریم میں عاد ارم کے نام سے موسوم ہے.چنانچہ سورۂ فجر میں فرمایا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ.اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ.الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (الفجر :۷ تا ۹).چونکہ یونانی نام کا پچھلا حصہ صرف اسم پر دلالت کرتا ہے اصل نام ادرم ہے اور چونکہ یونانی زبان میں عین نہیں ہے عین کو بھی الف لکھا جاتا ہے.اس لئے ادرم اصل میں عدرم ہے جو عادارم سے بگڑا ہوا ہے.اور میٹائی سے مراد حضر موت نہیں ہوسکتا بعض یورپین مصنفوں کا خیال ہے کہ اس لفظ سے مراد حضرموت ہے.لیکن یہ خیال ان کا درست نہیں کیونکہ اول تو حضرموت ایک شہر کا نام ہے.اور یہ نام ایک قبیلہ کا بتایا گیا ہے.دوسرے حضرموت کا شہر یونانی اور لاطینی دونوں کتب میں مذکور ہے اور ان میں کسی جگہ بھی اس کا نام ان حروف میں
Page 291
نہیں لکھا گیا بلکہ یونانی کتب میں ہمیشہ حضرموت ADRAMOTITAI لکھا جاتا ہے.یعنی ادراموٹی ٹائی اور اوپر کا نام ادرامی ٹائی ہے.اسی طرح لاطینی میں حضر موت کو CHATRAMOTITAI لکھا جاتا ہے.یعنی شتراموتی تائی پس اس لفظ سے حضرموت کا شہر مراد لینا کسی صورت میں بھی درست نہیں ہوسکتا.اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم خیال کریں کہ اس خاص موقع پر جغرافیہ والوں نے پرانے یونانی اور لاطینی لفظ کو ترک کرکے ایک نیا لفظ ایجاد کرلیا.پھر اس سے بھی بڑا ثبوت یہ ہے کہ جس کتاب میں یہ لفظ آیا ہے اس میں ساتھ ہی حضرموت کا بھی حال لکھا ہوا ہے.جس سے معلوم ہوتاہے کہ اس کتاب کے مصنف کے نزدیک بھی یہ دونوں نام علیحدہ علیحدہ چیزوں کے تھے.(دیکھو العرب قبل الاسلام الجزء الاول صفحہ ۶۲ زیر عنوان عاد و ارم ذات العماد) اس قبیلہ کی تاریخ قرآن کریم کی رو سے قرآن کریم سے اس قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے عاد ارم ذات العماد تھے (۱) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ.اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ.الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ.(الفجر:۷ تا ۹)یعنی عاد جن میں سے اس وقت ہم ارم کا ذکر کرتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور ان کو ایسی طاقت حاصل تھی کہ ان کے بعد عرب میں کسی قوم کو اس قدر طاقت حاصل نہیں ہوئی.ارم قبیلے کے متعلق تاریخ سے یہ امر یقینی طور پر ثابت ہوچکا ہے کہ ان کی نہایت زبردست حکومت تھی.جو کہ پانچویں صدی قبل مسیح تک قائم رہی(ارض القرآن جلد ۱ صفحہ ۸۲).عبرانی زبان کی بحث کرتے ہوئے محققین السنہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ارمیک بھی ایک زبان تھی جس کے الفاظ عبرانی کے ساتھ بہت ملتے جلتے تھے اور یہ ارم قوم کی زبان تھی اور اس ارم قوم کی زبردست حکومت تھی جو سامی حکومت کے بعد قائم ہوئی.اپنے زمانہ حکومت میں یہ لوگ سارے عراق فلسطین شام اور کالدی علاقے پر حاکم ہو گئے تھے.بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان علاقوں سے باہر بھی نکل گئے تھے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Semetic Languages)(انگریزی میں کالدی کو CHALDIA کہتے ہیں) غرض مذکورہ بالا آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاد کی وہ قوم جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے ارم نامی تھی.اور ارم کا پتہ آثارِ قدیمہ سے لگ چکا ہے.قوم عاد حضرت نوح ؑکے بعد والی قو م ہے (۲)وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ (اعراف :۷۰) اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قوم حضرت نوح کی قوم کے معاً بعد گزری ہے.پس معلوم ہوا کہ تاریخوں میں جو سامی وغیرہ دوسری قوموں کا ذکر ہے جو کہ ارم سے پہلے حاکم تھیں وہ بھی عاد ہی کا حصہ تھیں.قوم عاد بلند مقامات پر اپنی یادگاریں بنایا کرتی تھی (۳)سورہ شعراء (ع۷) میں فرماتا ہے
Page 292
اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ(عاد:۱۲۹).کہ تم ہر اونچی جگہ پر نشان کھڑا کرتے ہو.یعنی MONUMENT بناتے ہو.اس آیت سے عاد کی ایک اور نشانی کا پتہ لگتا ہے اور وہ یہ کہ عاد قوم اونچے مقامات پر یادگاریں قائم کرنے کی عادی تھی.چنانچہ عرب میں بعض نہایت پرانی بڑی بڑی عمارتیں اب بھی ملتی ہیں.(ارض القرآن جلد ۱ صفحہ ۹۳) عدن سے چند میل کے فاصلے پر میں نے بھی بعض اونچی اونچی عمارتیں دیکھی ہیں.جو اونچے ٹیلے پر بنی ہوئی ہیں.ان عمارتوں میں حوض وغیرہ بھی تھے.یہ دورانِ سفر یورپ کا واقعہ ہے اس وقت میرے ہم راہیوں میں سے بھی بعض میرے ساتھ تھے.(۴) سورہ احقاف (ع۳) میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰۤى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ(احقاف:۲۶).اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کی تاریخ پوشیدہ ہو گئی ہے.صرف ان کی بڑی بڑی عمارتوں کے آثار باقی رہ گئے ہیں.قوم عاد احقاف میں رہتی تھی (۵)قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کے مقام کا بھی پتہ دیتا ہے چنانچہ فرماتا ہے.وَ اذْكُرْ اَخَا عَادٍ١ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ (احقاف :۲۲) اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کر جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا تھا.احقاف لغت کے لحاظ سے ریت کے ٹیڑھے ترچھے ٹیلوں کو کہتے ہیں(مفردات امام راغب زیر مادہ حقف).اور اصطلاح عرب میں دو علاقوں کو کہتے ہیں.جو خود تو شاداب ہیں لیکن صحرا کے پاس ہیں.صحرا سے ریت اڑاڑ کر ان علاقوں میں ٹیلے بنادیتی ہے.ان دو علاقوں میں سے ایک تو عرب کے جنوب کی جانب ہے یہ علاقہ جو جنوبی احقاف کے نام سے موسوم ہے یمن سے شروع ہوکر صنعاء کے نیچے نیچے عدن سے اوپر مشرق کی طرف کو چلا گیا ہے.پھر وہاں سے پھیلتا ہوا شمال کی جانب کو نکل گیا ہے.دوسرا علاقہ شمالی احقاف ہے جو بصریٰ سے نیچے کی طرف عراق کے بیابان کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے.یہ بھی ممکن ہے کہ جس وقت عذاب آیا ہو اس وقت اس علاقہ میں ٹیلے نہ ہوں بلکہ بعد میں اسی عذاب کے وقت صحرا کی ریت کے آنے کے سبب سے وہاں ٹیلے بن گئے ہوں.اور اس وجہ سے اس قوم کی تاریخ مخفی ہو گئی ہو.صحرا کی ریت کے ٹیلوں کو اگر صاف کیا جائے تو بالکل ممکن ہے کہ نیچے سے ایسے آثار نکلیں جن سے قوم کی تاریخ پر مزید روشنی پڑسکے.قوم عاد آندھی سے ہلاک ہوئی (۶)عاد کی ہلاکت کی خبر قرآن کریم یوں دیتا ہے.اَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّ ثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ١ۙ حُسُوْمًا١ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى١ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ.(الحاقۃ :۷،۸) اور عاد کا یہ حال ہوا کہ انہیں ایک تیز حد سے نکل جانے والی ہوا سے جسے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہلاکت کے لئے چلایا تھا ہلاک کیا گیا.یہ ہوا سات دن تک بلاوقفہ خدا تعالیٰ کے حکم سے چلتی رہی.یہاں
Page 293
تک کہ تو اس قوم کو اس ہوا کے اثر کے نیچے اس طرح گرا ہوا دیکھے گا کہ گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درخت ہیں.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد کے ملک پر ایک تیز آندھی آئی تھی.جو سات دن تک متواتر چلتی رہی.اور ان کے بڑے بڑے شہر اس آندھی کی زد میں آکر زیرخاک ہو گئے.اور اس طرح اس قوم کا زور ٹوٹ گیا.اور زوال شروع ہو گیا.اس آیت سے خیال پڑتا ہے کہ ابھی زیر خاک ان کے آثار باقی ہیں.تبھی تو فرمایا ہے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى.اور یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احقاف اس علاقہ کا نام اس تباہی کے بعد پڑا.کیونکہ آندھی کے سبب سے شہر ریت کے تودوں میں دب گئے اور علاقہ میں ٹیلے ہی ٹیلے نظر آنے لگ گئے.يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا١ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اے میری قوم میں اس( کا م) کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگوں گا.میرا اجر اس (ہستی )کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا ہے الَّذِيْ فَطَرَنِيْ١ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۰۰۵۲ (اور) کسی کے ذمہ نہیں ہے.(تو) کیا پھر (بھی) تم عقل سے کام نہیں لو گے (اور باوجود اس کے ایمان نہیں لاؤ گے) حلّ لُغَات.فَطَرَ فَطَرَ یَفْطُرُفَطْرًا اَلشَّیْءَ شَقَّہٗ.اس چیز کو پھاڑا.اَلْعَجِیْنَ اِخْتَبَزَہٗ مِنْ سَاعَتِہِ وَلَمْ یُخَمِّرْہُ.جب آٹے کے متعلق یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گوندھتے ہی روٹی پکالی.خمیر نہ ہونے دیا.اَ لْاَمْرَ اِخْتَرَعَہٗ وَابْتَدَعَہٗ وَاَنْشَاَہٗ.اس کام کو شروع کیا.یابغیر سابقہ مثال کے کیا.الصَّائِمُ فَطْرًا وَفِطْرًا وَفُطُوْرًا اَکَلَ وَشَرِبَ وَقِیْلَ اِبْتَدَأَ الْاَکْلَ وَالشُّرْبَ.روزہ دار نے پیا اور کھایا یا یہ کہ خالی پیٹ کھایا اور پیا.(اقرب) تفسیر.انبیاء کا دنیا سے استغناء اور خدا تعالیٰ کے حضور میں نیاز مندی پہلے حصہ آیت میں استغناء ظاہر کیا ہے.اور نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے.لیکن دوسرے حصہ میں اپنے عجز اور محتاجی کو ظاہر کیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کا بھوکا ثابت کیا ہے.اور خدا کے بندوں کا یہی مقام ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ سب دنیا سے مستغنی ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس قدر عجز و انکسار سے گرتے ہیں کہ ان سے زیادہ محتاج ہی کوئی نظر نہیں آتا.
Page 294
تک کہ تو اس قوم کو اس ہوا کے اثر کے نیچے اس طرح گرا ہوا دیکھے گا کہ گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درخت ہیں.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد کے ملک پر ایک تیز آندھی آئی تھی.جو سات دن تک متواتر چلتی رہی.اور ان کے بڑے بڑے شہر اس آندھی کی زد میں آکر زیرخاک ہو گئے.اور اس طرح اس قوم کا زور ٹوٹ گیا.اور زوال شروع ہو گیا.اس آیت سے خیال پڑتا ہے کہ ابھی زیر خاک ان کے آثار باقی ہیں.تبھی تو فرمایا ہے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى.اور یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احقاف اس علاقہ کا نام اس تباہی کے بعد پڑا.کیونکہ آندھی کے سبب سے شہر ریت کے تودوں میں دب گئے اور علاقہ میں ٹیلے ہی ٹیلے نظر آنے لگ گئے.يٰقَوْمِ لَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا١ؕ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اے میری قوم میں اس( کا م) کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگوں گا.میرا اجر اس (ہستی )کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا ہے الَّذِيْ فَطَرَنِيْ١ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۰۰۵۲ (اور) کسی کے ذمہ نہیں ہے.(تو) کیا پھر (بھی) تم عقل سے کام نہیں لو گے (اور باوجود اس کے ایمان نہیں لاؤ گے) حلّ لُغَات.فَطَرَ فَطَرَ یَفْطُرُفَطْرًا اَلشَّیْءَ شَقَّہٗ.اس چیز کو پھاڑا.اَلْعَجِیْنَ اِخْتَبَزَہٗ مِنْ سَاعَتِہِ وَلَمْ یُخَمِّرْہُ.جب آٹے کے متعلق یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گوندھتے ہی روٹی پکالی.خمیر نہ ہونے دیا.اَ لْاَمْرَ اِخْتَرَعَہٗ وَابْتَدَعَہٗ وَاَنْشَاَہٗ.اس کام کو شروع کیا.یابغیر سابقہ مثال کے کیا.الصَّائِمُ فَطْرًا وَفِطْرًا وَفُطُوْرًا اَکَلَ وَشَرِبَ وَقِیْلَ اِبْتَدَأَ الْاَکْلَ وَالشُّرْبَ.روزہ دار نے پیا اور کھایا یا یہ کہ خالی پیٹ کھایا اور پیا.(اقرب) تفسیر.انبیاء کا دنیا سے استغناء اور خدا تعالیٰ کے حضور میں نیاز مندی پہلے حصہ آیت میں استغناء ظاہر کیا ہے.اور نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو پاک قرار دیا ہے.لیکن دوسرے حصہ میں اپنے عجز اور محتاجی کو ظاہر کیا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کا بھوکا ثابت کیا ہے.اور خدا کے بندوں کا یہی مقام ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ سب دنیا سے مستغنی ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس قدر عجز و انکسار سے گرتے ہیں کہ ان سے زیادہ محتاج ہی کوئی نظر نہیں آتا.
Page 295
ایمان لانے سے قوموں کی ظاہری حالت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے.اور اگر کوئی قوم اپنے تنزل کے وقت اس وقت کے رسول پر ایمان لے آئے تو اسے زندگی کا ایک اور دور عطا ہو جاتا ہے.اسی کی طرف اشارہ ہے.ان الفاظ میں کہ تمہاری قوت پر اور قوت کا اضافہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوجائے گا.قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِكِيْۤ اٰلِهَتِنَا انہوں نے کہااے ہود تو ہمارے پاس (اپنے دعویٰ کا) کوئی روشن ثبوت نہیں لایا اور ہم (محض) تیرے کہہ دینے عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ۰۰۵۴ سے اپنےمعبودوں کو چھوڑ دینے والے نہیں ہیں اور نہ( ہی) ہم تیرا کہا ماننے والے ہیں.حلّ لُغَات.عَنْ حَرْفٌ جَرٍّ.وَلَہٗ تِسْعَۃُ مَعَانٍ.عَنْ حرفِ جر ہے اور اس کے نو معنی ہوتے ہیں.الرَّابِعُ التَّعْلِیْلُ.چوتھے معنی اس کے اظہار علت و باعث کے ہیں.جیسے عَنْ مَّوْعِدَۃٍ کے معنی وعدہ کی وجہ سے کے ہیں.(اقرب) تفسیر.عاد کا ہود کی بات کے برے معنی لینا شریر آدمی اچھی بات کے بھی برے ہی معنی لیتا ہے.ایسے اخلاص کی نصیحت کا مطلب ان لوگوں نے یہی لیا کہ یہ شخص ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے.اور یہی جواب دیا کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے.اور تیرے فرمانبردار نہیں ہوسکتے.شرک جیسی بے ثبوت بات کے ماننے والے ایک روشن بات کا ثبوت مانگتے ہیں پھر تعجب اس دلیری پر ہے کہ شرک جیسی بے دلیل بات کے پیچھے پڑتے ہوئے حضرت ہودؑ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تو اپنے دعویٰ کی دلیل دے.حالانکہ شرک کے مدعی تو وہ خود تھے.دلیل ان کو دینی چاہیےتھی نہ کہ شر ک کے منکر کا فرض تھا کہ وہ دلیل پیش کرتا.ان کے اس فقرہ سے تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ خدا تعالیٰ کے سوا معبود بنالیتے ہیں جوکہ بالکل ہی بے دلیل دعویٰ ہے اور دوسری طرف جب اس کے خلاف دلائل پیش کئے جاتے ہیں تو اپنے مخالف سے کہہ دیتے ہیں کہ تم تو کوئی دلیل ہی نہیں لاتے.گویا وہ بڑے ہی دلیل کے پابند ہیں.کوئی بات انہوں نے کبھی بغیر دلیل کے مانی ہی نہیں.حضرت ہود کی توہین عَنْ قَوْلِكَ میں کس قدر توہین مقصود ہے الفاظ تھوڑے ہیں مگر تذلیل کوٹ کوٹ کر بھری
Page 296
ہوئی ہے.کہ تو بھی کوئی ہستی رکھتا ہے کہ صرف تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں.اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ١ؕ قَالَ اِنِّيْۤ (تیرے متعلق) ہم سوائے اس کے (کچھ) نہیں کہتے کہ ہمارے کسی معبود نے تجھ پر کوئی آفت ڈال دی ہے.اس اُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اشْهَدُوْۤا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَۙ۰۰۵۵مِنْ نے کہا میں اللہ (تعالیٰ) کو( اس بات کا) گواہ ٹھیراتا ہوں.اور تم( بھی) گواہ رہو کہ جس کو تم (اللہ کا) شریک دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ۰۰۵۶ ٹھہراتے ہو اس سے میں بیزار ہوں.(جو) اس (خدا) کے سوا (ہیں) اس لئے تم سب (اکٹھے ہو کر) میرا مقابلہ کرو اور مجھے مہلت (بھی) نہ دو.حلّ لُغَات.اِعْتَرَاہُ.اِعْتَرَاہُ غَشِیَہٗ طَالِبًا مَعْرُوْفَہٗ اس کے ساتھ چمٹا رہا کہ اس کے احسان کو حاصل کرے.اِعْتَرٰی فُلَانًا اَمْرٌ اَصَابَہٗ.وہ بات اسے لگ گئی چمٹ گئی.(اقرب) تفسیر.ہود کے منکرین کا اعتراض مطلب یہ ہے کہ چونکہ تو ہمارے معبودوں کو نہیں مانتا تھا اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے.اور تیری عقل ماردی ہے.ہود کا جواب اس اعتراض کا حضرت ہود نے کیا لطیف جواب دیا ہے کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے کسی بت نے میرا دماغ بگاڑ دیا ہے تو اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ میں ان سارے بتوں کے خلاف ہوں اور ان سے کلی طور پر بیزار ہوں.یعنی اگر تمہارے خیال میں تمہارے بعض بتوں نے کسی بات سے ناراض ہوکر مجھ پر وبال نازل کیا ہے تو لو اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں ان سب کے خلاف ہوں.اور ان کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے ان سب باتوں سے بیزار ہوں.پس اگر ان میں کچھ طاقت ہے تو میری ایسی شدید بیزاری کے بعد وہ جو کچھ میرے خلاف کرسکتے ہیںکرلیں.خدا تعالیٰ کی شہادت سے مراد اس کے نشانات کی شہادت ہے اِنِّيْۤ اُشْهِدُ اللّٰهَ میں یہ فرمایا کہ تم نے عقلی دلائل سے تو فائدہ نہیں اٹھایا اب میں خدا تعالیٰ کی عملی شہادت کو پیش کرتا ہوں.اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے
Page 297
نشانات سے سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کرکے دکھادے.اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ١ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ میں نے یقینا ً اللہ پر جو میرا (بھی) رب (ہے) اور تمہارا (بھی )رب ہے بھروسہ کیا ہے (روئے زمین پر) کوئی بھی اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا١ؕ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۰۰۵۷ چلنے والا (جاندار) ایسا نہیں کہ وہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے نہ ہو.میرا رب یقیناً سیدھی راہ پر (کھڑا اور اپنی طرف آنے والوں کی حفاظت کر رہا) ہے.حلّ لُغَات.نَاصِیَۃٌ النَّاصِیَۃُ.قُصَاصُ الشَّعَرِ اَیْ حَیْثُ تَنْتَہِیْ نِبْتَتُہٗ مِنْ مُقَدَّمِہٖ اَوْمُؤَخَّرِہٖ.یعنی سر کی اگلی یا پچھلی طرف جہاں بال ختم ہوجاتے ہوں وہاں کے بالوں کا گچھا.یعنی بالوں کا مجموعہ.وَقِیْلَ النَّاصِیَۃُ مُقَدَّمُ الرَّأْسِ.بعض کے نزدیک نَاصِیَۃ سر کے اگلے حصہ کو کہتے ہیں وَقَالُوْا اَلطُّرَّۃُ ھِیَ النَّاصِیَۃُ.اور بعض نے طرّہ ہی کو نَاصِیَۃ قرار دیا ہے.اس کی جمع نَاصِیَاتٌ اور نَوَاصِیْ ہے.اَذَلَّ فُلَانٌ نَاصِیَۃَ فُلَانٍ أَیْ عِزّہٗ وَشَرَفَہٗ فلاں شخص نے فلاں کی عزت اور بزرگی کو خاک میں ملا دیا.نَوَاصِیُ النَّاسِ.اَشْرَافُھُمْ وَالْمُتَقَدِّمُوْنَ مِنْھُمْ.نَوَاصِیْ کے معنی قوم کے بزرگوں اور لیڈروں کے بھی ہوتے ہیں.وَھٰذَا کَمَاوُصِفُوْا بِالذَّوَائِبِ.یُقَالُ فُلَانٌ ذُ ؤَابَۃُ قَوْمِہٖ وَنَاصِیَۃُ عَشِیْرَتِہٖ.اور یہ استعمال ایسا ہی ہے جیسے ذَوَائب (مینڈھیوں) کا لفظ بھی سرداران قوم کے لئے آتا ہے.عرب میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی قوم کی مینڈھی اور اپنے قبیلے کی چوٹی ہے.یعنی اپنی قوم کا سردار ہے.(اقرب) تفسیر.اخذ ناصیہ کے متعلق عرب کا دستور اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا.عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم کو کوئی فتح ہوتی تھی تو قیدیوں کو بادشاہ کے سامنے لایا جاتا تھا.اور وہ یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ میں فاتح بادشاہ ہوں اور تم مفتوح ہو ان کے اگلے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیتا تھا اور یہ بھی عرب کا رواج تھا کہ جس پر رحم کرنا ہوتا تھا اس کے اگلے بال مونڈ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا.تو اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا کے دونو معنے ہوسکتے ہیں.(۱) کہ کوئی دابۃ نہیں جس کی ناصیۃ خدا تعالیٰ نے نہ پکڑی ہوئی ہو یعنی جو خدا تعالیٰ کے ماتحت نہ ہو اور (۲) یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک کے بال مونڈے ہوئے ہیں.یعنی اللہ تعالیٰ نے احسان کرکے تم کو چھوڑا ہوا ہے.ورنہ تم تباہ ہو جاتے.غرض انسان کو
Page 298
توجہ دلائی ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور تصرف ہے اور یہ کہ تم صرف اس کے فضل سے زندگی بسر کررہے ہو ورنہ تمہارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ تم کو زندہ رکھا جاسکے.جب میرا سہارا میرا اور تمہارا رب ہے تو تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو رَبِّيْ وَ رَبِّكُمْ کہہ کر یہ بتلایا ہے کہ جس سے میرا تعلق ہے وہ تمہارا بھی مالک ہے اور میرا بھی مالک ہے.پس جب میرا تعلق تمہارے مالک سے ہے تو پھر تم سے جو اس کے غلام ہو مجھے کیا ڈر ہوسکتا ہے.کیونکہ جب آقا کسی کا دوست ہو جاتا ہے تو پھر غلاموں کی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے آقا کے دوست کو کوئی نقصان پہنچاسکیں.اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ کے معنی اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍکہہ کر فرمایا کہ جو سیدھے راستے پر چلے اسی کو خدا مل سکتا ہے.مشرک تو ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے.وہ اسے کہاں پاسکتا ہے.دوسری بات یہ بتائی ہے کہ تم تو مجھے مارنا چاہتے ہو جیسا کہ لَا تُنْظِرُوْنِ میں اس کی طرف اشارہ تھا.تو خدا تعالیٰ بھی سیدھے راستے پر میری طرف مدد کے لئے آرہا ہے.یعنی قریب سے قریب راہ سے میری مدد کے لئے آرہا ہے.سیدھے راستے سے مراد قریب کا راستہ ہی ہے.کیونکہ سیدھا راستہ ہمیشہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے.فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّاۤ اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَيْكُمْ١ؕ وَ پھر اگر تم (میری طرف سے) پیٹھ پھیر لو تو( اس میں میرا کوئی نقصان نہیں کیونکہ) جو بات دے کر مجھے تمہاری طرف يَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ١ۚ وَ لَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْـًٔا١ؕ اِنَّ بھیجا گیاہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دی (ہوئی ہے)اور( اگر تم ایسا کرو گے تو) میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ۰۰۵۸ (پہلوں کا) جانشین بنادے گا اور تم اس کو کچھ (بھی) نقصان نہیں پہنچا سکو گے میرا رب یقیناً ہر چیز کا محافظ ہے.حلّ لُغَات.تَوَلّٰی تَوَلَّوْا اصل میں تَتَوَلَّوْا ہے اس کے شروع میں حرف ت کے مکرر آنے کی وجہ سے عربی کے قاعدہ کے مطابق ایک ت کو حذف کر دیا گیا ہے.تَوَلّٰی کے معنی پیٹھ پھیرنے کے ہوتے ہیں.تفسیر.پیغام کے ردکیے جانے کا نقصان پیغامبر کونہیں پہنچتا نادان لوگ خیال کرتے ہیں
Page 299
کہ اگر وہ نبی کے پیغام کو رد کرتے ہیں تو اس سے اس نبی کو نقصان پہنچاتے ہیں حالانکہ پیغامبر کو پیغام کے رد ہونے سے کیا نقصان ہوسکتا ہے؟ نقصان ہوگا تو یا پیغام بھیجنے والے کا ہوگا یا اس کا جس کی طرف پیغام بھیجا گیا ہو.پس حضرت ہودؑ فرماتے ہیں کہ میں تو پیغامبر ہوں مجھے تو نقصان اسی صورت میں ہوسکتا تھا کہ میں پیغام حق نہ پہنچاتا اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا.سو اس سے میں محفوظ ہوں.میں نے پیغام پوری طرح پہنچا دیا ہے.اس پیغام کو رد کرنے میں تمہارا ہی نقصان ہے اب اگر نقصان کا احتما ل ہوسکتا ہے تو پیغام بھیجنے والے کو یا جس کی طرف پیغام دیا گیا ہے اسے.سو پیغام دینے والے کا یہ حال ہے کہ وہ تمہارا محتاج نہیں کہ اس کی بات رد ہوجانے کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے.اس کی بات تو خود تمہارے فائدہ کے لئے تھی.اگر تم نہ مانو گے تو کوئی اور قوم اس بات کو مان کر ترقی کر جائے گی.بہرحال اس کا پیغام ضائع نہیں ہوسکتا.کیونکہ جس بات کو وہ چاہتا ہے اس کی حفاظت بھی کیا کرتا ہے.اب جس امر کا اس نے ارادہ کیا ہے اور جو تعلیم میری معرفت اس نے دی ہے اس کی بھی وہ ضرور حفاظت کرے گا.اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی یونہی جانے نہیں دے گا.وہ اس کے حضور میں محفوظ ہیں اور ضرور ان اعمال کے متعلق تم سے بازپرس ہوگی.وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ اور جب ہمارا( عذاب کا) حکم آگیا تو (اس وقت) ہم نے ہود کو اور جو( لوگ) اس کے ساتھ (ہو کر) اس پر ایمان بِرَحْمَةٍ مِّنَّا١ۚ وَ نَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ۰۰۵۹ لائے تھے ان کو( اس عذاب سے) اپنی (خاص) رحمت کے ذریعہ سے نجات دی اور ایک سخت عذاب سے ہم نے انہیں بچالیا.تفسیر.اللہ تعالیٰ کی عام سنت یہ ہے کہ جب کوئی وبا یا تکلیف ملک میں آتی ہے تو اچھے برے سب ہی اس میں شریک ہوجاتے ہیں لیکن انبیاء کے زمانہ میں چونکہ عذابوں کا نزول اتمام حجت کے طور پر ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں کے لئے خاص جوش میں آجاتی ہے.اور باوجود ایک ہی ملک اور ایک ہی جگہ میں رہنے کے وہ اکثر قسم کے عذابوں سے کلی طور پر یا جزوی طور پر محفوظ رہتے ہیں.اسی کی طرف رَحْمَةٍ مِّنَّا کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک خاص اور اہم فضل تھا اور عام قانون قدرت کے ماتحت نہ تھا.
Page 300
عذاب غلیظ سے کیا مراد ہے عَذَابٍ غَلِيْظٍ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس عذاب سے باوجود کوشش کے آزاد نہیں ہوسکیں گے.کیونکہ گاڑھی چیز میں جب کوئی پھنس جائے تو اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے.نہ وہ ٹھوس ہوتی ہے کہ اس پر سہارا دے کر نکل آئے اور نہ پتلی ہوتی ہے کہ اس میں سے چل کر نکل جائے.جس طرح دلدل کہ اس میں پھنسا ہوا باہر نہیں نکل سکتا.وَ تِلْكَ عَادٌ١ۙ۫ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهٗ اور یہ (مغرور لوگ) عاد( کی قوم کے لوگ) تھے انہوں نے (دیدہ و دانستہ) اپنے رب کے نشانوں کا انکار کردیا اور وَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ۰۰۶۰ اس کے رسولوںکی نافرمانی کی اور ہر ایک سر کش (اور) حق کے دشمن (شخص) کے حکم کی پیروی کی.حلّ لُغَات.جَـحَدَ.جَـحَدَیَـجْحَدُ جُحُوْدًا.حَقَّہٗ وَبِحَقِّہٖ اَنْکَرَہٗ مَعَ عِلْمِہٖ بِہٖ.اس نے اس کے حق کا باوجود یہ جاننے کے کہ اس کا مجھ پر حق ہے انکار کر دیا.کَفَرَہٗ وَکَذَّبَہٗ اس کی بات کا انکار کیاا ور اسے جھوٹا قرار دیا.جَبَّارٌ اَلْجَبَّارُمِنْ صِفَاتِ اللہِ تَعَالٰی.جَبَّار کا لفظ خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ہے.(یعنی اصلاح کرنے والا) وَکُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ اور ہر سرکشی کرنے والے اور بات نہ ماننے والے کو بھی کہتے ہیں.(اقرب) اَلْعَنِیْدُ اَلْمُخَالِفُ لِلْحَقِّ الَّذِیْ یَرُدُّہٗ وَھُوَیَعْرِفُہٗ جَمْعُہٗ عُنُدٌ.حق کا مخالف جو اسے جانتے ہوئے رد کرے.اس کی جمع عُنُدٌ ہے.(اقرب) تفسیر.تِلْکَ کے اشارہ کی وجہ تِلْکَ سے عاد کی بڑائی کی طرف اشارہ ہے کہ عاد ایسی زبردست قوم تھی مگر باوجود اس کے جب انہوں نے شوخی اور شرارت سے کام لیا اور حق کا جان بوجھ کر اور ضد سے انکار کر دیا اور جو ان کی بھلائی کا پیغام لائے تھے ان کی بات تو نہ مانی لیکن جو لوگ دنیا میں زور اور جبر کرنے والے تھے اور بلاوجہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا مول لیا کرتے تھے ان کی بات مان لی اور باوجود اس کے حریت کادعویٰ بھی رکھتے تھے
Page 301
وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ١ؕ اَلَاۤ اِنَّ اور اس دنیا میں (بھی) لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہےاور قیامت کے دن( بھی لگا دی جائے گی) سنو !عاد نے عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ١ؕ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍؒ۰۰۶۱ یقیناً اپنے رب (کے احسانوں) کی ناشکری کی تھی سنو !عاد یعنی قوم ہود کے لئے (قرب الٰہی سے) دوری ہے.حل لغات.بُعْدًا اَلْبُعْدُ ضِدُّ الْقُرْبِ.دوری.اللَّعْنُ.لعنت خدا کے قرب سے محرومی.(اقرب) تفسیر.لعنت کے معنی جب لعنت کا فعل بندوں کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی لعنت کرنے کے ہوتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی دور کردینے کے ہوتے ہیں.پس مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ دیدار الٰہی سے محروم رہیں گے اور خدائےتعالیٰ کا قرب نہیں پائیں گے.اَلَا حرف تنبیہ کے لانے کی وجہ اَلَاۤ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ.یہ جملہ نہایت ہی دلکش ہے اَ لَا تنبیہ کے لئے آتا ہے.پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنو !سنو! عاد نے اپنے رب کا انکار کر دیا.یعنی یہ کس قدر اندھیر کی بات ہے کہ عاد نے اپنے پرورش کرنے والے کی بات ماننے سے انکار کر دیا.حالانکہ اپنے محسن کی بات کی شریف لوگ قدر کیا کرتے ہیں.رب کے معنی ہیں پیدا کرکے پھر ادنیٰ حالت سے ترقی دے کر کمال تک پہنچانے والا.پس اس امر پر اظہار افسوس کیا ہے کہ جس نے ان کو اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا شان و شوکت کے حصول کے بعد اسی کی بات ماننے سے انکار کر دیا.جو ایک طرف تو ناشکری کا فعل ہے اور دوسری طرف بے وقوفی پر دلالت کرتا ہے.کیونکہ جس نے بڑھایا ہے گرا بھی سکتا ہے.چنانچہ کان کھول کر سن لو! کہ آخر عاد سے یہی معاملہ ہوا.ہود ؑ کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد کردیئے گئے.وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا١ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ اور ثمود کی طرف( ہم نے) ان کے بھائی صالح کو (بھیجا تھا) اس نے (انہیں) کہا اے میری قوم تم اللہ( تعالیٰ) کی مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ١ؕ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے اسی نے تمہیں زمین سے اٹھایا (اور بلندی بخشی) اور اس میں
Page 302
اسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ١ؕ اِنَّ رَبِّيْ تمہیں آباد کیا اس لئے تم اس سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف کامل رجوع اختیار کرو میرا رب یقیناً قریب ہے قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ۰۰۶۲ (اور دعا ئیں) قبول کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.اِسْتَعْمَرَ اِسْتَعْمَرَہٗ فِی الْمَکَانِ.جَعَلَہٗ یَعْمُرُہٗ.اسے مقرر کیا کہ وہ مکان کو آباد کرے (اقرب) اور اقرب میں بحوالہ اساس لکھا ہے اِسْتَعْمَرَاللہُ عِبَادَہٗ فِی الْاَرْضِ طَلَبَ مِنْہُمْ الْعِمَارَۃَ فِیْہَا.اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چاہا کہ وہ زمین کو آباد کریں.تفسیر.ثمود عرب تھے یہاں صالح کا لفظ صاف بتاتا ہے کہ ثمود عربی امت تھے کیونکہ صالح عربی زبان کا لفظ ہے.عاد بھی عرب تھے اور چونکہ قرآن شریف یہ فرماتا ہے کہ قوم ثمود عاد کی قائم مقام تھی جیسا کہ فرمایا وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا.پس معلوم ہوا کہ یہ عاد بھی ایک عربی نژاد امت تھی.صالح کا نام بطور ترجمہ نہیں ہوسکتا شاید یہ خیال کیا جائے کہ صالح کا لفظ کسی دوسری زبان کے نام سے ترجمہ کرکے اختیار کیا گیا ہے لیکن یہ درست نہیں ہوسکتا کیونکہ تمام غیرعربی اسماء بغیر ترجمہ کے ہی قرآن مجید میں مندرج ہیں.جیسے موسیٰ، ہارون، یونس، زکریا.پس یقیناً یہ نام انہی کی زبان کا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عاد اور ثمود دونوں عربی قومیں تھیں.قوم نوح بھی عرب تھی اور چونکہ عاد کو نوح کی قوم کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوح بھی عرب ہی کے کسی علاقہ میں مبعوث ہوئے تھے اور عربی نسل سے ہی تعلق رکھتے تھے.چنانچہ تاریخ سے حضرت نوح کا مقام عراق میں ہی ثابت ہے.اور عرب قوم ابتداء میں اس علاقہ میں حکومت کرتی رہی ہے.عربی زبان اُمُّ الاَلْسِنَۃ ہے ان باتوں کے بیان کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ابتدائے عالم کی زبان عربی تھی.کیونکہ جب نسل انسانی کا آغاز عرب سے مانا جائے تو اس ملک کی زبان کو بھی ام الالسنۃماننا پڑے گا.
Page 303
سامری زبان عربی زبان کی ایک شاخ تھی نہ کہ اصل یورپ کی تحقیقات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ابتداء میں ایک زبان سامری نام کی تھی.اس سے عربی زبان نکلی اور پھر اس کےاندر مختلف تغیرات سے اور زبانیں پیدا ہوگئیں اور یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ سامری زبان عرب کے جنوب میں بولی جاتی تھی مگر حق یہ ہے کہ عراق اور عرب کی مختلف زبانیں درحقیقت عربی زبان کی شاخیں ہیں.اَنْشَاَكُمْ کے معنی هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو زمین سے پیدا کیا تھا کیونکہ زمین سے پیدائش صرف حضرت آدمؑ کے زمانہ میں ہوئی تھی.بعدازاں سلسلہ تناسل جاری کیا گیا.اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ادنیٰ تھے.زمینی تھے اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل تھے خدا نے تم کو اٹھایا ترقی دی اعلیٰ بنایا حکومت عطا کی.پس زمین سے پیدا کرنے کے الفاظ سے مقصود ادنیٰ حالت سے ابھارنے اور اٹھانے پر زور دینا ہے.فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ادنیٰ حالت سے ترقی دے کر زمین میں تہذیب و شائستگی کے پھیلانے کا کام سپرد کیا.پس چاہیےکہ اس عظیم الشان ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اپنی خطاؤں پر استغفار کرو تاکہ اگر تم سے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی نقص رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.اس صورت میں اللہ تعالیٰ تم پر اور بھی فضل کرے گا.انسان اپنی ترقی کے لئے ہر آن خدا کے فضل کا محتاج ہے اس آیت میں یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی رہتی ہے.پس انسان کو یاد رکھنا چاہیےکہ اس کی پیدائش کی بنیاد کمزوری پر ہے.اور اس کی ترقی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے.پس چاہیےکہ اس کی طرف رجوع کرتا رہے.تاکہ اس سے تازہ بتازہ فیضان حاصل کرکے اپنی ترقی کو قائم رکھ سکے.ورنہ قطع تعلق کی صورت میں وہ آپ ہی آپ پھسل کر اپنی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے گا.قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌکے معنی قَرِیْبٌ کہہ کر بتایا ہے کہ اگر اس کے پیغام کا انکار کروگے تو وہ بہت جلد سزا بھی دے سکتا ہے.کیونکہ اس کی افواج کے آنے میں دیر نہیں لگتی.اور مُـجِیْبٌ کے لفظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ شاید کسی کو خیال ہو کہ گو وہ قریب ہے لیکن وہ بندوں کے کاموں میں دخل نہیں دیتا.مگر یہ خیال غلط ہوگا وہ بندوں کے کاموں میں دخل دیتا ہے اور جو لوگ اسے پکارنے والے ہوں ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی پکار پر ان کی امدا دکے لئے فوراً آتا ہے.
Page 304
قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَاۤ اَتَنْهٰىنَاۤ انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے( تو)تو ہمارے درمیان( آئندہ کے لئے) امید کی جگہ (سمجھا جاتا) تھا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَ اِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا ( اب) کیا تو (باوجوداس عقل و دانش کے) ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ایسی چیز کی عبادت کریں جس کی تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ۰۰۶۳ ہمارے باپ (دادے) کرتے آئے ہیں اور (سچ تو یہ ہے کہ) جس بات کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے متعلق ہم ایک بے چین کر دینے والے شک میں (پڑے ہوئے) ہیں.حلّ لُغَات.اَرَابَہُ یُرِیْبُہٗ اِرَابَۃً شَکَّکَہٗ وَجَعَلَ فِیْہِ رِیْبَۃً.اس کے دل میں شک ڈال دیا.اَرَابَہٗ مِنْہُ أَمْرٌأَ سَاءَ بِہِ الظَّنَّ وَلَمْ یَسْتَیْقِنْ مِنْہُ الرِّیْبَۃَ اس کی نسبت بدگمانی کی.اَرَابَکَ فُلَانٌ.بَلَغَکَ عَنْہُ الشَّیْءُ اَوْتَوَھَّمَتْہُ.تجھے اس سے کوئی شکایت پہنچی.یا تو نے اس کے متعلق کسی شکایت کا خیال کیا.زَیْدًا اَقْلَقَہٗ وَاَزْعَـجَہٗ.قَالَ الْمُتَنَبِّیْ....مَااَرَابَکَ مَنْ یُّرِیْبُ اسے گھبرا دیا اور فکر میں ڈال دیا.چنانچہ متنبی نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے اور لکھا ہے کہ جس بات نے تجھے بے چین کر دیا ہے اس نے کس شان کے انسان کو بے چین اور بے قرار کیا ہے.(اقرب) تفسیر.حضرت صالح کے متعلق ان کی قوم کی پہلے سے امیدیں اور حقیقۃً ان کا پورا ہونا صالح علیہ السلام کی قوم شاکی ہے کہ ہم تو تیرے ذہن رسا اور خدا داد طاقتوں کو دیکھ کر امید لگائے بیٹھے تھے کہ تو قوم کے لئے طاقت اور قوت کا موجب ہوگا لیکن تو تو الٹا قوم کو تباہ کرنے لگا ہے.مگر قوم نے یہ نہ خیال کیا کہ ان کی امیدیں جو صالح کے متعلق تھیں وہ تو پوری ہوگئیں اور فی الواقع وہ قوم کے لئے مفید وجود بن گئے لیکن ان کی امیدیں اپنی ذاتوں کے متعلق پوری نہ ہوئیں اور اس مفید تحریک سے جو صالح ؑ کے ذریعہ سے قائم ہوئی تھی وہ محروم رہ گئے.انسان بھی کس قدر کمزور ہے وہ کبھی امید لگاتا ہے اور وہ امید پوری ہوجاتی ہے مگر عین اس وقت جب اس کی برسوں کی بلکہ اس کی قوم کی صدیوں کی امیدی پوری ہونے لگتی ہیں وہ منہ موڑ کر چلا جاتا ہے.اور جو چشمہ اس کے گھر سے پھوٹا
Page 305
تھا دوسرے اس سے سیراب ہوتے ہیں.یہی نظارہ پھر اس وقت ظاہر ہورہا ہے.مسلمان ایک آنے والے کے منتظر تھے وہ آ گیا.اور دوسری قومیں اس سے فائدہ اٹھارہی ہیں مگر وہ ہیں کہ ابھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لئے تیار نہیں.شکوک دور کرنے والی تعلیم ثمود کے لئے شکوک کا موجب کیوں بنی؟ اَتَنْهٰىنَاۤ.کیا تو ہمیں باپ دادوں کے طریق عبادت سے روکتا ہے.یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ تو باپ دادا کی عزت کو بلند کرے گا مگرتو تو الٹا ان کی جڑیں کاٹنے لگ گیا ہے.جب انسان کے اندر بیماری ہو تو اس کے منہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے.چونکہ ان لوگوں کے دل خراب ہوگئے تھے وہی تعلیم جو شکوک کو دور کرنے کے لئے آئی تھی اسی کی نسبت کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس کی وجہ سے شکوک سے بھر گئے ہیں.حضرت صالح کی قوم کا یہ کہنا کہ ہمیں تو تجھ پر بہت سی امیدیں تھیں صرف لالچ دلانے کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس کی طرف سے جس قدر مامور آتے ہیں وہ سب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے لوگوں کے دلوں پر اپنی قابلیت اور نیکی سے گہرا اثر پیدا کرلیتے ہیں اور یہ امر ضروری ہوتا ہے کیونکہ شروع دعویٰ میں نہ ابھی پیشگوئیاں پوری ہوئی ہوتی ہیں اور نہ تعلیم مکمل ہوئی ہوتی ہے.اس وقت ان کی گزشتہ زندگی ہی ان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور حضرت خدیجہؓ اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت زیدؓ اس دلیل کی بنا پر بغیر کسی نشان و معجزہ اور تفصیلی تعلیم کے سننے کے آپ پر ایمان لے آئے.قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ اس نے کہا اے میری قوم بتاؤ اگر میں (فی الواقع اپنے دعویٰ کی بنا) اپنےرب کی طرف سے (عطا شدہ) کسی روشن اٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ ثبوت پررکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے ایک (خاص) رحمت عطا کی ہے تو( باوجود اس کے )اگر میں اس
Page 306
عَصَيْتُهٗ١۫ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ۠ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ۰۰۶۴ کی نافرمانی کروں تو اللہ (تعالیٰ) کے مقابل پر کون میری مدد کرے گا پھر( اس وقت تو) تم مجھے سوائے تباہی میں ڈالنے کے (اور) کسی بات میں نہیں بڑھاؤ گے.حلّ لُغَات.نَصَرَنَصَرَ فُلَانًا مِنْ عَدُوِّہٖ نَجَّاہُ مِنْہُ وَخَلَّصَہٗ وَاَعَانَہٗ وَقَوَّاہُ عَلَیْہِ (اقرب) یعنی جب نَصَرَ کا صلہ مِنْ ہو تو اس کے معنی مدخول مِنْ کے خلاف کسی کو مدد دینے کے ہوتے ہیں.پس اس کے معنی ہوئے اسے اس کے دشمن کے مقابل پر مدد دی.اور اس سے بچا لیا.خَسَّرَہٗ جَعَلَہٗ یَخْسِرُ.اسے گھاٹے میں ڈال دیا نَسَبَہٗ اِلَی الْخُسْرَانِ.اسے گھاٹا پانے والا قرار دیا.ا.ضَلَّہُ اسے گمراہ کیا.اَھْلَکَہُ اسے ہلاک کیا.(اقرب) تفسیر.حضرت صالح کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اس تعلیم کی وجہ سے ہمیں شبہات پیدا ہورہے ہیں اور اگر تو اسے پیش نہ کرتا تو ہم تجھے اپنا لیڈر بنانے کے لئے تیار تھے سوچو تو سہی کہ اگر میں فی الواقع خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں تو اس کی تعلیم کو چھوڑ کر تمہاری لیڈری مجھے کیا نفع پہنچا سکتی ہے.اس صورت میں تمہاری امداد تو میرے لئے نقصان ہی نقصان کے سامان پیدا کرے گی.وَ يٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اور اے میری قوم یہ( اونٹنی) درانحالیکہ تمہارے لئے (میری سچائی کا)ایک نشان ہے اللہ (تعالیٰ ہی) کی( طرف اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ منسوب ہوسکنے والی) اونٹنی ہے.اس لئے تم اسے (آزاد پھرتی )رہنے دو کہ اللہ کی زمین میں (چل پھر کر) کھائے قَرِيْبٌ۰۰۶۵ (پیئے) اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں ایک جلد آنے والا عذاب پکڑ لے گا.حلّ لُغَات.ذَرْ.ذَرْہُ اَیْ دَعْہُ.چھوڑ دے کہتے ہیں ذَرْہ وَ اَحْذَرْہُ اسے چھوڑ دے اور اس سے بچ.(اقرب)
Page 307
تفسیر.صالح کی اونٹنی کے متعلق تفسیروں میں بے سرو پا روایات صالح کی اونٹنی مدت سے انسانی قوت متخیلہ کے لئے ایک کھیل بن رہی ہے.مفسرین نے ہر قسم کی روایات اس کے متعلق جمع کردی ہیں.جن میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ حضرت صالح ؑ نے کفار کے مطالبہ پر دعا کرکے پہاڑ کے پیٹ سے ایک اونٹنی پیدا کی تھی اور جب وہ پیدا ہوئی اس وقت وہ حاملہ بھی تھی اور پھر فوراً اس کے بچہ بھی پیدا ہو گیا(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا).اور اسی قسم کی بے سروپا روایات جو عربوں میں مشہور تھیں انہوں نے تفسیروں میں نقل کردی ہیں اور یہ نہیں خیال کیا کہ ناواقف لوگوں پر ان روایات کا کیا اثر پڑے گا؟ اس اونٹنی کی پیدائش کا معجزانہ ہونا ثابت نہیں حقیقت یہ ہے کہ اونٹنی کی پیدائش کے معجزانہ ہونے کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے.بلکہ سورۂ شعراء میں فرماتا ہے قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ۠.مَاۤ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا١ۖۚ فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ.وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.(الشعراء:۱۵۴تا۱۵۷) منکرین صالح نے کہا کہ تو صرف دھوکہ خوردہ ہے تو فقط ہمارے جیسا ایک آدمی ہے.پس اگر تو سچا ہے تو کوئی نشان لے آ.اس پر صالح نے کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے اسے بھی اپنی باری پر پینے کا حق ہے.اور تم کو بھی ایک مقرر دن پر اپنی باری کا پانی پینا ہوگا.اور تم اسے کوئی تکلیف نہ دینا.نہیں تو تم کو ایک بڑے دن کا عذاب پہنچے گا.ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹنی کی پیدائش نشان کے طور پر نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کی آزادی کو ایک نشان قرار دیا گیا تھا.اور اسے مارنے والے کے لئے عذاب مقرر تھا.اگر اس کی پیدائش ایک نشان ہوتی تو صالح ؑ کفار کے مطالبہ پر کہتے کہ پہلے تمہارے مطالبہ پر یہ اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوچکی ہے.لیکن بجائے اس کے وہ ان کے مطالبہ کے جواب میں اونٹنی کی آزادی کو آئندہ آنے والے نشان کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں.اونٹنی کس طرح نشان تھی اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اونٹنی نشان کس طرح تھی؟ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو استاذی المکرم حضرت مولوی نورالدین صاحب رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے کہ عرب اور دوسرے ممالک میں دستور تھا کہ بادشاہ اپنی طاقت کے اظہار کے لئے کوئی جانور چھوڑ دیا کرتے تھے اور اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اسے کوئی کچھ نہ کہے.اگر کوئی کچھ کہتا تو وہ اسے تباہ کر دیتے تھے.اس طریق کی نقل میں حضرت صالح ؑ نے اپنی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشان مقرر کیا کہ تمہاری دیرینہ رسم کے مطابق اس اونٹنی کو بھی نشان مقرر کیا جاتا ہے.اگر تم اسے دکھ دو گے تو وہ الٰہی گورنمنٹ کا مقابلہ سمجھا جائے گا اور تم عذاب میں مبتلا کئے جاؤگے.
Page 308
کیا اونٹنی کو آزاد چھوڑنا نبی کی شان کے منافی نہیں ہے ان معنوں پر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جو اس قسم کے جانور چھوڑے جاتے تھے وہ بطور سانڈھ کے ہوتے تھے اور ان کو چھیڑنا یا کھیتوں سے روکنا ناجائز سمجھا جاتا تھا.اور یہ امر ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ ایک جانور کو چھوڑ دے کہ لوگوں کے کھیتوں کو کھاتا پھرے.اور روکنے والوں کو عذاب کی دھمکی دے.سو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ایک نبی کی شان کے یہ خلاف ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر امر میں پرانی رسم کی اتباع کی جائے.افتادہ زمینوں میں آزادی سے چرنا مراد ہے نہ کہ لوگوں کے کھیتوں میں حضرت صالح ؑ نے یہ شرط نہیں کی تھی کہ جس کی کھیتی میں یہ جانورچاہے گھس جائے.بلکہ صرف یہ شرط رکھی تھی کہ عام افتادہ زمینوں میں یہ چرے گی.وہاں اسے نہ چھیڑا جائے.چنانچہ اس آیت میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہفَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ اللّٰهِ اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے.پس لوگوں کے کھیتوں میں اونٹ چرانے کا اعلان حضرت صالح ؑ نے نہیں کیا تھا.بلکہ صرف افتادہ زمینوں میں جن کا کوئی مالک نہ تھا اور جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے تصرف میں تھیں کہ اس کے اوپر بادل برس کر وہاں گھاس اگا دیتے تھے کسی کو ان کی سرسبزی کے لئے کچھ نہ کرنا پڑتا تھا.تبلیغ کے لئے آزادی سے پھرنا بھی مراد ہو سکتا ہے میرے نزدیک اس نشان کا یہ مفہوم بھی ہوسکتا ہے کہ کسی دیرینہ رسم کی طرف اشارہ نہ ہو بلکہ حضرت صالح ؑ کا یہ مطلب ہو کہ تبلیغ کے لئے مجھے ادھر ادھر پھرنے دو اور اس میں روک نہ ڈالو.اور یا’’ خدا کی زمین میں چرنے دو‘‘ کے یہ معنی ہوں کہ ضروریات دینی کے پورا کرنے کے لئے جو میں مختلف علاقوں میں پھروں تو اس میں روک نہ ڈالو.اور یہ مجاز مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے اور مراد سوار کا روکنا ہوتا ہے.حالانکہ روکا سواری کو جاتا ہے.بسا اوقات جب ایک مسافر کو لوگوں نے کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس کی سواری کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے ان کی مراد سواری کو نہیں بلکہ سوار کو روکنا ہوتی ہے.اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ حضرت صالح ؑ کے تبلیغی سفروں میں روک ڈالتے ہوں گے اور ادھر ادھر پھرنے نہیں دیتے ہوں گے اس پر خدا تعالیٰ نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ صالح ؑکی اونٹنی کو ادھر ادھر پھرنے دو.مطلب یہ کہ صالح ؑ کے سفروں میں روک نہ ڈالو.جہاں چاہے وہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر چلا جائے.اور خدا کا کلام پہنچائے.چونکہ وہ لوگ بھی اس کلام کے مطلب کو سمجھتے تھے انہوں نے حضرت صالح ؑ کی اونٹنی کو مار دیا.اور گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہا کہ ہم تم کو اپنے ملک میں تبلیغ کرنے کی عام اجازت نہیں دے سکتے.جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے.ایک تیسرے معنی بھی میرے نزدیک اس آیت کے ہوسکتے ہیں اور وہ یہ کہ حضرت صالح نے تجربہ سے جب
Page 309
معلوم کیا کہ ان کا دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا فساد کا موجب ہوتا ہے اور عوام الناس سے ملنے کا زیادہ موقع چشموں اور جانور چرانے کی وادیوں میں ہی ہوتا ہے اس لئے انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم سے فساد دور کرنے کے لئے ایسا انتظام کیا کہ جو عام چراگاہ تھی اس سے اپنے جانوروں کو روک دیا اور کوئی دوسری افتادہ زمین جو ان کی قوم کی ملکیت نہ تھی اس امر کے لئے منتخب کرلی اسی طرح اونٹنی کو پانی پلانے کے لئے بھی انہوں نے عام وقت جو پانی پلانے کا تھا اسے چھوڑ دیا.اور دوسرا وقت جس وقت لوگ پانی نہیں پلاتے تھے مقرر کرلیا.اور پھر اعلان کر دیا کہ فساد سے بچنے کے لئے ہم نے ہر ممکن تدبیر اختیار کرلی ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بھی ایسی جگہوں اور وقتوں کو چھوڑ دیا ہے جن میں تم لوگوں سے مل کر فساد کا اندیشہ ہوسکتا ہے.لیکن اگر اب بھی آپ لوگوں نے فساد کیا تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ آپ لوگ ہماری زندگی کو ہی پسند نہیں کرتے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر نازل ہوگا.وادی فَـجُّ النَّاقَۃ ان معنوں کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ پرانی تاریخوں سے ایک وادی کا پتہ لگتا ہے جس کا نام فَـجُّ النَّاقَۃِ تھا اور حضرت مسیح سے ڈیڑھ سو سال قبل کے ایک جغرافیہ میں بھی اس کا ذکر ہے.پرانے یونانی مورخ اسے بیڈاناٹا لکھتے تھے.جو فَـجُّ النَّاقَۃِ کا ہی بگڑا ہوا ہے.اس قدیم وادی سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صالح ؑ نے اپنی قوم سے الگ ایک وادی اپنی اونٹنی کے چرانے کے لئے مقرر کرلی تھی.تاکہ ان کا جانور دوسرے جانوروں سے اور چرواہا دوسرے چرواہوں سے نہ ملیں اور آپس میں فساد کی صورت پیدا نہ ہو.لیکن آپ کے مخالفوں کو اس پر بھی صبر نہ آیا اور انہوں نے وہاں جاکر بھی آپ کی اونٹنی کو مار ڈالا.اور اللہ تعالیٰ کے اعلان کی بے حرمتی کرکے عذاب میں گرفتار ہوئے.محض اونٹنی کو مارنا قوم کی تباہی کا موجب کیونکر ہوا؟ یہ خیال نہیں کرنا چاہیےکہ ایک اونٹنی کے مارنے پر قوم کو کیوں تباہ کر دیا.کیونکہ اونٹنی کے مارنے کے معنے یہ تھے کہ ہم صالح کو کسی جگہ بھی آرام سے نہیں رہنے دیں گے اور اس کے سفر کے ذریعوں کو مسدود کردیں گے اور یہ امر شدید ترین دشمنی پر دلالت کرتا ہے.اس کی سزا سے ایسی قوم جو پہلے تعلیم الٰہی کا انکار کرکے مجرم ہو چکی ہو نہیں بچ سکتی.فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ١ؕ ذٰلِكَ اس پر انہوں نے (تلوار سے) اس کی ٹانگیں کاٹ دیں جس پر اس نے (ان سے) کہا تم تین روز (کی مہلت میں
Page 311
لفظ ہے.سورۂ نحل میں ہے کہ ہم نے انہیں بالکل ہلاک کردیا.اور ذاریات میں صَاعِقَۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.جس کے معنی بجلی اور عذاب کے ہیں.الحاقہ میں عذاب کا ذریعہ طَاغِیَۃ کو قرار دیا گیا ہے.جس کے معنی حد سے نکل جانے والے کے ہیں.سورۂ قمر میں صَیْحَۃ کا لفظ اور ضُحٰی میں دَمْدَمَ عَلَیْہِمْ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.مگر ان سب الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں.جن الفاظ میں بظاہر اختلاف ہے وہ رَجْفَۃٌ.صَیْحَۃٌ.صَاعِقَۃٌ اور طَاغِیَۃٌ ہیں.لیکن صَیْحَۃٌ صَاعِقَۃٌ اور طَاغِیَۃٌ تینوں کے معنی عذاب کے بھی ہیں.پس اگر زلزلہ سے وہ قوم ہلاک ہوئی ہو تو سب الفاظ بغیر اختلاف کے چسپاں ہوجاتے ہیں.کیونکہ زلزلہ بھی عذاب اور ہلاکت کا ذریعہ ہے.كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا١ؕ اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ١ؕ گویا انہوں نے ان میں زندگی نہیں گزاری تھی سنو ثمود نے اپنے رب (کے احسانوں) کی نا شکری کی اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَؒ۰۰۶۹ تھی سنو ثمود کے لئے( قرب الٰہی سے) دوری ہے.حلّ لُغَات.غَنِیَ یَغْنٰی غَنِیَ فُلَانٌ عَاشَ.زندہ رہا.زندگی گزاری.(اقرب ) تفسیر.اس جگہ پر بُعْدً الِثَمُوْدَ قَوْم صَالِحٍ نہیں کہا گیا.جیسا کہ اس سے پہلے رکوع کے آخر میں لِعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍکہا گیا تھا.اس سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیےکہ پہلی آیت میں ہود کی زیادتی قافیہ کے لئے کی گئی تھی.مگر اس جگہ چونکہ قافیہ نہیں بنتا تھا.اس لئے صالح کا نام ساتھ نہیں لیا گیا.ایسا نہیں کیونکہ قرآن کریم ہرگز قافیوں کی وجہ سےا لفاظ نہیں بڑھایا کرتا.اس فرق کی ایک تاریخی وجہ ہے اور وہ یہ کہ عاد دو قوموں کا نام ہے.ایک عاد اولیٰ اور دوسری عاد ثانیہ کہلاتی ہے.پس اگر خالی بُعْدًا لِعَادٍ کہہ دیا جاتا تو یہ اشتباہ پڑتا کہ کیا عاد سے مراد پہلی قوم عاد ہے یا دوسری.یا دونوں.اس لئے وہاں قوم ہود کہہ کر بتا دیا کہ اس آیت میں عاد سے عاد اولیٰ مراد ہے.نہ کہ عاد ثانیہ.اس کے برخلاف ثمود صرف ایک قوم کا نام ہے.اور اس کے متعلق دھوکے کا احتمال نہیں ہوسکتا تھا.اس وجہ سے ثمود کے ساتھ قوم صالح کے الفاظ نہیں بڑھائے کیونکہ ان الفاظ کے بڑھانے سے کوئی خاص غرض پوری نہیں ہوتی تھی.ثمود اور صالح کے حالات پر تاریخی روشنی ثمود کا ذکر یونانی تاریخوں میں بھی آتا ہے.اور ان میں مسیح ؑ کے زمانہ کے قریب ان کا ذکر ہے.اور انہوں نے ثمود کا مقام حجر بتایا ہے.جسے وہ اپنے رسم الخط میں اگرا کرکے لکھتے
Page 312
ہیں.اور ثمود کا نام ان کے جغرافیوں میں تمودینی (THAMUDENI) آتا ہے.اور حجر کے پاس وہ ایک جگہ کا ذکر کرتے ہیں جسے عرب ان کے بیان کے مطابق فج الناقہ کہتے تھے.بتلیموس جو ۱۴۰ سال قبل مسیح ہوا ہے وہ لکھتا ہے کہ حجر کے پاس ایک جگہ ہے جس کا نام (BADANATA) ہے(العرب قبل الاسلام صفحہ ۶۴).فتوح الشام کا مصنف ابواسماعیل لکھتا ہے اِنَّ ثَمُوْدَاَمْلَأُ الْاَرْضَ بَیْنَ بُصْرٰی وَعَدَنْ فَلَعَلَّھَا کَانَتْ فِی طَرِیْقِ ھِجْرَتِہَا نَحْوَ الشَّمَالِ (العرب قبل الاسلام صفحہ ۶۵)کہ ثمود قوم بصریٰ (جو شام کا ایک شہر ہے) سے لے کر عدن تک پھیلی ہوئی تھی.اور وہیں ان کی حکومت تھی.شاید کہ وہ اس وقت جنوب سے شمال کی طرف ہجرت کررہے تھے.یعنی حمیر اور سباء کی طاقت کے زمانہ میں جب ان کو ہجرت کرنی پڑی تو اس وقت ایسا ہوا.ان دونوں قبیلوں کی حکومت نے یمن میں طاقت پکڑی تھی اور ثمود کی حکومت احقاف کے جنوب میں تھی.انہوں نے جب ان کو نکالا تو یہ اوپر کی طرف نکلنے شروع ہوئے.پہلے حجاز پھر تہامہ اور پھر حجر میں چلے گئے.تمدنِ عرب والا کہتا ہے کہ وَلَایَخْرُجُ الْحُکْمُ فِی ذٰلِکَ مِنَ التَّخْمِیْنِ یعنی یہ قیاسی بات ہے.(العرب قبل الاسلام صفحہ ۶۵) قوم ثمود جنوب سے ہجرت کرکے شمال کی طرف آئی تھی درحقیقت عربوں کا خیال ہے کہ ثمود بھی عاد کی ایک شاخ ہے.اور انہی کی طرح یہ یمن میں رہتی تھی.جب حمیر کی حکومت ہوئی تو انہوں نے ان کو حجاز کی طرف نکال دیا.لیکن اس کی تصدیق اب تک کسی دلیل سے نہیں ہوئی.کیونکہ اس قوم کے آثار اب تک جنوب میں نہیں ملے.حجر کو پرانے زمانہ سے مدائن صالح بھی کہتے ہیں.اور اس کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح کے زمانہ سے پہلے یہ نبطیوں کے ماتحت آچکا تھا.جنہیں انبات بھی کہتے ہیں.یہ لوگ بطرا کے رہنے والے تھے.جسے یونانی لوگ پیٹرا کہتے ہیں.چنانچہ اس جگہ کئی کتبے نبطی زبان کے ملے ہیں لیکن ان نبطی کتبوں کے ساتھ ساتھ بعض کتبے یمنی زبان میں بھی ملے ہیں.ان کتبوں کو مستشرقین کا گروہ ثمودیہ کے نام سے موسوم کرتا ہے.یعنی ثمود قوم کے کتبے.اس تحقیق سے عرب جغرافیہ نویسوں کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے کہ ثمود قوم جنوب سے ہجرت کرکے شمال کی طرف آئی تھی کیونکہ اگر وہ جنوب سے نہ آتی تو ان کی زبان یمنی زبان سے ملتی جلتی نہ ہوتی.قوم ثمود قوم عاد کے معاً بعد ہوئی حجر جو اس قوم کا دارالحکومت معلوم ہوتا ہے مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان میں ہے اور اس وادی کو جس میں حجر واقع ہے وادی قریٰ کہتے ہیں.اس علاقہ میں اس قوم کا زور تھا.جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ کہ ثمود نے وادی قریٰ میں پہاڑ کاٹ کاٹ کر مکان بنائے تھے.(الفجر:۱۰) قرآن کریم میں اس قوم کا زمانہ عاد کے معاً بعد بتایا ہے.کیونکہ فرماتا ہے.وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ
Page 314
ہیں) اس کے بعد اس کا کوئی نشان نہیں ملا(ارض القرآن جلد اول صفحہ ۱۸۳).اب اس زمانے (۱۸۳۴ء) میں ایک انگریز مستشرق (WELLESTED) نے پھر اس کا پتہ لگایا ہے اور وہ ایشاٹک سوسائٹی جرنل میں چھپ چکا ہے.اور فارسٹر نے (جو ایک انگریز مستشرق ہے.) اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے.اصل کتبہ حمیری زبان میں ہے.جو اصل میں جنوبی عربی زبان ہے.موجودہ مستشرقین نے اس کا نام حمیری رکھ لیا ہے.یہ کتبہ حصن غراب میں جو عدن کے قریب ہے ملا ہے.اس کتبہ کی عبارت کا ترجمہ اس کتبہ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے.(۱) ہم مدت تک اس وسیع قصر میں رہے.ہماری حالت بدنصیبی اور ادبار سے دور تھی.ہماری نہروں میں (۲) دریا کا پانی امڈ آتا تھا.سمندر موجیں مارتا ہوا ہمارے قلعہ کی دیواروں سے غضبناک ہوکر ٹکراتا تھا.ہمارے چشمے خوش آئند آواز سے بہتے تھے.(۳) بلند کھجوروں کے اوپر جن کے باغبان خشک چھوہارے ہماری وادیوں کے چھوہاروں کی زمینوں میں لگاتے تھے اور خشک چاول بوتے تھے.(۴) ہم پہاڑی بکروں کا اور جوان خرگوشوں کا شکار پنجروں اور جالوں سے کرتے تھے اور مچھلیوں کو (۵) بہلا بہلا کر باہر نکال لیتے تھے.اور ہم آہستہ آہستہ خرامان خراماں رنگ برنگ کے ریشم کے کپڑے اور لاہی سبز مختلف الالوان جامے پہن کر چلا کرتے تھے.اور ہم پر وہ بادشاہ حکومت کرتے تھے جو کمینہ خیالات سے بہت دور اور شریروں کو سزا دینے والے تھے.ہود کی شریعت کے مطابق.(۶)اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے.اور ہم معجزات کا یقین رکھتے تھے.قیامت کے روز اور نتھنوں کے راز پر ایمان تھا.(۷)راہزن گھس آئے اور وہ ہمارے ساتھ کچھ جھگڑا کرتے تھے.مگر ہم نے اپنے گھوڑوں کو پویہ ڈال دیا.اور ہمارے شریف نوجوان سخت اور نوکدار نیزوں کو لے کر آگے بڑھے.(۸)ہمارے خاندان کے مغرور بہادر مرد اور عورتیں گھوڑوں پر لڑ رہی تھیں جن کی گردنیں لمبی تھیں.اور جو چمکدار کمیت رنگ کے تھے.(۹)ہماری تلواریں بدستور دشمنوں کوز خمی کررہی تھیں اور چھید رہی تھیں.یہاں تک کہ ان کے قلب پر حملہ کرکے ان کو مغلوب اور بالکل پست کر دیا.جو بدترین نوع انسان میں سے تھے.اس کتبہ کی عبارت سے ثمود کے کیا حالات ثابت ہوتے ہیں اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان
Page 315
لوگوں میں ہر قسم کی تہذیب تھی.اور قوانین کے علاوہ فیصلہ جات بھی لکھے جاتے تھے.تاکہ آئندہ لوگوں کے لئے سند ہوں.جیسا کہ آج کل کی انگریزی عدالتوں کے فیصلوں کی رپورٹیں شائع ہوتی ہیں.یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ قوم جس کا ذکر کتبہ میں ہے حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے یا بعد میں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ہود کی امت میں سے ایک حصہ جنوبی عرب میں بھی رہ گیا ہو.بہرحال یہ ثابت ہے کہ یہ قوم ثمود میں سے تھی اور ان کی طرف یا ان کے ان بھائیوں کی طرف جو ہجرت کرکے شمال کو چلے گئے تھے صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے.یہ قوم میدانوں اور پہاڑوں پر بھی حکومت رکھتی تھی قرآن کریم کی عبارت تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا.(الاعراف:۷۵) سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میدانوں اور پہاڑوں دونوں پر اس قوم (ثمود) کی حکومت تھی.اسی طرح فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ.وَّ زُرُوْعٍ وَّ نَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ.(الشعراء :۱۴۸.۱۴۹) سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ملک چشموں والا اور باغات والا تھا.وہاں کھجوریں بھی اچھی قسم کی ہوتی تھیں اور زراعت بھی ہوتی تھی.غرض یہ کتبہ جس کا مضمون اوپر بیان ہوا حرف بہ حرف قرآن کریم کا مصدق ہے.یہ قوم اسلام سے پہلے بکلی مٹ چکی تھی حضرت صالح کے بعد جلدی ہی یہ قوم گرنے لگ گئی.کیونکہ اس کے زمانہ کے چند صدیوں بعد کے فاتح قوموں میں اس کا ذکر مفقود ہے.سرجون یا شرغون نامی اسیریا کے ایک بادشاہ نے جس کا زمانہ حکومت ۷۲۲ قبل مسیح سے ۷۰۵ قبل مسیح تک تھا عرب پر فوج کشی کی تھی.اس کی فتوحات میں ثمود کا نام آتا ہے اور اس نے اس کا ذکر ایک کتبہ میں کیا ہے.جو اس نے ایک فتح کی یادگار میں کندہ کرایا تھا.مورخین یونان میں ڈائدورس جو ۸۰ قبل مسیح ؑ گزرا ہے.پلینی جو ۷۹ قبل مسیح گزرا ہے اور بطلیموس جو ۱۴۰ قبل مسیح گزرا ہے تینوں نے اس قوم کا ذکر کیا ہے.جسٹینین بادشاہ روم نے جب عرب پر حملہ کیا ہے تو اس کی فوج میں تین سو ثمودی سپاہی بھی تھے لیکن اسلام سے پہلے اس قوم کا نام و نشان مٹ چکا تھا.(ارض القرآن صفحہ ۱۹۸) وَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا١ؕ اور ہمارے فرستادے یقیناً یقیناً ابراہیم کے پاس خوشخبری لائے (اور) کہا( ہماری طرف سے آپ کو) سلام ہو.اس نے قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ۰۰۷۰ کہا(تمہارے لئے ہمیشہ )سلامتی ہو.پھر( اس نے) ایک بھنے ہوئے بچھڑے کے لانے میں (کچھ بھی) دیر نہ لگائی.حلّ لُغَات.لَبِثَ لَبِثَ یُقَالُ مَالَبِثَ اَنْ فَعَلَ کَذَا.یعنی مَالَبِثَ کے معنی ہوتے ہیں بغیر دیر
Page 316
کے فوراً وہ کام کرلیا.مَاأَبْطَأَ فِی فِعْلِہٖ.اَوْ مَاتَأَخَّرَ عَنْ فِعْلِہٖ.اپنے کام میں دیر نہ لگائی (اقرب) اَلْعِجْلُ وَلَدُالْبَقَرَۃِ.گائے کا بچہ.وَقِیْلَ اَوَّلَ سَنَۃٍ اور بعض نے اسے ایک سال کی عمر تک کے لئے مخصوص قرار دیا ہے.(اقرب) اَلْـحَنِیْذُ اَلْحَنِیْذُ.اَلْمَشْوِیُّ.بھنا ہوا.وَفَسَّـَرہٗ اَ بُوْزَیْدٍ بِالنَّضِیْجِ.ابوزید نے اس کے معنی پکے ہوئے کے کئے ہیں.وَآخَرُ بِالّذِیْ یَقْطُرُ مَاءَ ہٗ بَعْدَ الشَّیْءِ اور بعض نے اس گوشت کے معنی کئے ہیں جس میں سے بھوننے پر پانی ٹپک رہا ہو.وَنَقَلَ الْاَزْھَرِیُّ عَنِ الْفَرَّاءِ.اَلْحَنِیْذُ.مَاحَفَرْتَ لَہٗ فِی الْاَرْضِ ثُمَّ غَمَمْتَہُ.وَھُوَ مِنْ فِعْلِ اَھْلِ الْبَادِیَۃِ اِلٰی اَنْ قَالَ وَالشِّوَاءُ الْمَحْنُوْذُ الَّذِیْ قَدْ اُلْقِیَتْ فَوْقَہُ الْحِجَارَۃُ الْمَرْضُوْفَۃُ بِالنَّارِ حَتّٰی یَنْشَوِیَ انْشِوَاءً شَدِیْدً افَیَتَھَرَّی تَـحْتَـھَا.یعنی ازھری نے فراء سے نقل کیا ہے کہ حَنِیْذٌ اس گوشت کو کہتے ہیں جسے گڑھا کھود کر اس میں رکھ دیا جائےاور اس پر تیز گرم کرکے پتھر رکھ دیئے جائیں یہاں تک کہ ان کی گرمی سے وہ گوشت پوری طرح پک جائے.(اقرب) تفسیر.یہاں حضرت ابراہیمؑ کا ذکر صرف استطرا ًدا ہے میں شروع سورۃ میں بتاچکا ہوں کہ حضرت ابراہیم ؑ کا ذکر اس سورۃ میں ضمناً ہے اور حضرت لوطؑ کا ذکر چھیڑنے کے لئے ہے.ورنہ اصل مقصود حضرت لوط ؑ کا ہی ذکر ہے.جن کی قوم تباہ کی گئی تھی.کیونکہ اس سورۃ میں انہی اقوام کا ذکر ہو رہا ہے.جو تباہ کر دی گئی تھیں.حضرت ابراہیم ؑکے ذکر کی وجہ حضرت ابراہیم ؑ کا ذکر لوط ؑ کے ذکر کے ابتداء میں اس لئے کیا ہے کہ حضرت لوط ؑ حضرت ابراہیم ؑ پر ایمان لانے والوں میں سے تھے اور ان کے تابع نبی تھے.جس طرح حضرت اسحاق اور اسماعیل ان کے تابع تھے.یا ہارون حضرت موسیٰ کے تابع تھے.گوامتی نہ تھے.کیونکہ اس وقت نبوت براہ راست ملا کرتی تھی نہ کہ نبی متبوع کے فیض سے.اس قسم کی نبوت صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جاری ہے کہ تابع نبی ایک لحاظ سے نبی ہوتا ہے اور دوسرے لحاظ سے امتی.اس انذار کے ساتھ بیٹے کی بشارت کو کیوں ملایاگیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ چونکہ متبوع نبی تھے اور حضرت لوط ؑ نبوت سے پہلے ان پر ایمان لائے تھے اور ان کے ساتھ ہجرت کرکے شام کے ملک میں آئے تھے اس لئے ان کی قوم کی تباہی کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم کو دینی مناسب سمجھی.اور اسی وجہ سے لوط ؑ کا ذکر کرنے سے پہلے اس خبر کا ذکر کر دیا.جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط کی تباہی کے متعلق دی تھی.مگر اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھو کہ چونکہ یہ خبر حضرت ابراہیم ؑ کو نبی متبوع ہونے کی حیثیت سے دی جارہی تھی اور
Page 317
براہ راست اس خبر سے حضرت ابراہیم ؑکا تعلق نہ تھا اس لئے ان کی تکلیف کو ایک بشارت کے ساتھ ملا دیا.تاکہ ایک بدقوم کی تباہی کی خبر کے ساتھ ایک نیک نسل کی ابتداء کی خبر کو ملا کر صدمہ کو کم کر دیا جائے.یہ رسل کون تھے؟ یہ رسل کون تھے.اس کے متعلق اختلاف ہے.بعض لوگ انہیں انسان قرار دیتے ہیں.اور بعض ملائکہ قرار دیتے ہیں.میرے نزدیک بھی یہ لوگ آدمی ہی تھے گو ان کی نیکی کی وجہ سے بعض نے انہیں ملک کہا ہے.جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت آتا ہے اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ (یوسف :۳۲) ان لوگوں کے فرشتہ ہونے کے خلاف یہ آیت ہےقُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنَ۠ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا (بنی اسرائیل :۹۶) اس آیت سے دو استدلال ہوتے ہیں.(۱)فرشتے رسول ہوکر نیک لوگوں کے لئے آتے ہیں.نہ کہ بدکاروں کے لئے.پس اس طرح انسانی شکل میں ایک بدکار شہر کے سامنے ان کا ظاہر ہونا اس آیت کے خلاف ہے.(۲) دوسرے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک انسان کو بھی فرشتہ کہا جاتا ہے.کیونکہ اس میں بتایا ہے کہ اگر اس دنیا میں ملائکہ بستے لیکن مراد انسانوں سے ہے.کیونکہ ملائکہ سے مراد ملائکہ ہوتے تو ان کی طرف رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ ملائکہ تو احکام الٰہی کے تابع ہوتے ہی ہیں.یہ بشارت حضرت ابراہیم ؑکو بلا واسطہ کیوں نہ دی گئی اگر یہ سوال ہو کہ کیوں براہ راست حضرت ابراہیمؑ کو ہی یہ الہام نہ ہوا دوسروں کی معرفت کیوں یہ خبر دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ المؤمن یَرٰی وَیُرٰی لَہٗ.(سنن ابن ماجہ ابواب تعبیر الرؤیا باب الرؤیا الصالحة ) کبھی مومن کو براہ راست خبر دی جاتی ہے کبھی دوسرے کی معرفت.چونکہ ان لوگوں کو کسی خاص غرض کے ماتحت حضرت لوط کے پاس جانے کا حکم ملا تھا اور یہ خبر انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کو بھی پہنچانی تھی اس لئے حضرت ابراہیمؑ کے رنج کو دور کرنے کے لئے یہ بشارت بھی انہی کی معرفت بھیجی گئی.کیوں دوسرے لوگوں کے ذریعے سے حضرت لوط کو یہ خبر دی گئی وہ خاص غرض کیا تھی جس کے سبب سے ان لوگوں کو خبر دے کر حضرت لوط ؑ کے پاس بھیجا گیا.اس کا یقینی پتہ تو کلام الٰہی سے نہیں لگتا.مگر میرے نزدیک ایک وجہ ظاہر ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط اس علاقہ میں باہر سے آکر بسے تھے اس وجہ سے بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند مقامی نیک لوگوں کو الہام کرکے بھیجا تاکہ وہ تباہی سے پہلے حضرت لوط ؑ کو کسی محفوظ اور مناسب جگہ کی طرف لے جائیں اور انہیں تکلیف نہ ہو.یہ انذار پہلی دفعہ کا نہیں تھا اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ نبی کو تو انذار نہ ہوا ہو مگر
Page 318
دوسروں کو ان کی قوم کے متعلق انذار ہوا ہو.اور پھر بغیر اس کے کہ قوم کو توبہ کا موقع دیا گیا ہو عذاب آ گیا ہو.تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا.لیکن حضرت لوط کے معاملہ میں بھی ایسا نہیں ہوا.کیونکہ دوسروں کی معرفت خبر دینے سے میری یہ مراد نہیں کہ انذار ہی ان کی معرفت ہوا تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ وقت عذاب کی خبر ان کی معرفت دی گئی.ورنہ عذاب کی خبر تو پہلے سے مل چکی تھی اور انذار ہوچکا تھا.سورۂ قٓ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ اَصْحٰبُ الرَّسِّ وَ ثَمُوْدُ.وَ عَادٌ وَّ فِرْعَوْنُ وَ اِخْوَانُ لُوْطٍ.وَّ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَ قَوْمُ تُبَّعٍ١ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ(قٓ :۱۳ تا ۱۵).اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پہلی قوموں کے لئے ایک عرصہ پہلے سے انذار ہوچکا تھا اسی طرح حضرت لوط کے مخاطبین کے لئے بھی انذار ہوچکا تھا.پس جو کچھ بالواسطہ ہوا وہ صرف یہ ہے کہ حضرت لوط کی تسلی کے لئے عین عذاب کے وقت اس کے نزول کے قرب کی خبر چند علاقہ کے واقف لوگوں کی معرفت ان کو پہنچائی گئی.تاکہ وہ لوگ حضرت لوط کو اپنے ساتھ لے کر مناسب جگہ تک پہنچا دیں.پہلے انذار ہوچکنے کا ثبوت بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ سے بھی نکلتا ہے.(الحجر :۶۴) اس آیت میں وہ خبر لانے والے لوگ مقر ہیں کہ جو خبر آپ پہلے دے چکے ہیں اور جس کے متعلق یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے تھے ہم اسی کا وقت بتانے آئے ہیں.سلامٌ اور سلاماً کے معنی قَالُوْا سَلٰمًا میں سلاما سے پہلے نُسَلِّمُ کا فعل محذوف ہے.یعنی آنے والوں نے سلام کہا کہ ہم سلام کرتے ہیں.حضرت ابراہیم ؑ کے جواب میں سلام یا تو مبتداء ہے اور علیکم اس کی خبر محذوف ہے یعنی تم پر سلامتی ہو اور یا پھر مبتدا محذوف ہے.یعنی جوابی کا لفظ.اور مراد یہ ہے کہ میرا جواب بھی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو.سلام کا جواب حضرت ابراہیم نے بہتر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اس تعلیم کا کیا ہی عمدگی سے لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو کوئی دعا کرے اس سے بہتر دعا اس کے لئے کی جائے.آنے والوں نے سَلَامًا کہا تھا.جو جملہ فعلیہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا.جو اپنے محذوف کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے اور جملہ اسمیہ اپنے معنوں میں جملہ فعلیہ سے قوی ہوتا ہے اور اس کے معنوں میں دوام پایا جاتا ہے گویا انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تم پر بھی ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے.حضرت ابراہیمؑ کی مہمان نوازی ایک اور سبق بھی اس آیت سے ملتا ہے اور وہ مہمان نوازی کا سبق ہے.حضرت ابراہیمؑ نے ان لوگوں کے آتے ہی بغیر کسی مزید سوال و جواب کے بچھڑا ذبح کرکے ان کے آگے لا رکھا.اور
Page 319
یہ نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں یا نہیں.یا ابھی کھانا کھائیں گے یا ٹھہر کر.مہمان نوازی اسلام کے اصول میں سے ہے مگر افسوس کہ دوسری قوموں کے اثرات کے نیچے مسلمان بھی اب اس فرض سے غافل ہوتے جاتے ہیں.حالانکہ ان کے نبی کی سنت ان کے لئے اسوۂ حسنہ کے طور پر موجود ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں تو سبھی خوبیاں موجود تھیں مگر وہ باتیں جو آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہؓ کو خاص طور پر محسوس ہوئیں ان میںسے ایک آپ کی مہمان نوازی کی صفت بھی تھی.چنانچہ جب پہلی وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ گھبرا کر گھر تشریف لائے.اور حضرت خدیجہؓ سے نزول وحی کا ذکر گھبراہٹ میں کیا.تو انہوں نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی.کلا واللہ لَایُخْزِیْکَ اللہُ اَبَدًا اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْکَلَّ وَتَکْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِی الضَّیْفَ وَتُعِیْنُ عَلَی نَوَائِبِ الْحَقِّ.(صحیح بخاری کتاب بدءالوحی باب کیف کان بدء الوحی) یعنی ایسا کبھی نہیں ہوسکتا.اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز کبھی رسوا نہ ہونے دے گا.کیونکہ آپ رشتہ داری کے تعلقات کا ہمیشہ پاس رکھتے ہیں لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں دنیا سے اٹھ چکے ہوئے اخلاق حمیدہ کو ازسر نو عدم سے وجود میں لاتے ہیں.مہمان نوازی کرتے ہیں.اور حق کے خلاف پیش آمدہ حوادث کا مقابلہ کرتے اور ستم رسیدوں کی حمایت کرتے ہیں.کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ مہمان نوازی اسراف میں داخل ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسراف سے کام لیا.کہ چند آدمیوں کے لئے بچھڑا ذبح کر دیا.لیکن یہ اسراف نہیں وہ جنگل میں رہتے تھے اور اس جگہ نہ قصاب تھا نہ پرچون کا دوکاندار کہ بازار سے سودا خرید کر کھانا تیار کرتے.وہ جانور پالتے تھے پس ان کی مہمان نوازی یہی ہوسکتی تھی کہ دنبہ یا بچھڑا جو اس وقت پاس ہو ذبح کرکے مہمانوں کے لئے تیار کر دیں.فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَ اَوْجَسَ پس جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس( کھانے) تک نہیں پہنچتے تو اس نے( سمجھا) کہ میں نے انہیں نہیں پہچانا اور مِنْهُمْ خِيْفَةً١ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍؕ۰۰۷۱ ان (کے اس رکنے کی وجہ) سے خطرہ محسوس کیا (اس پر) انہوں نے کہا (کہ) تو خوف نہ کر ہمیں (تو) لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے.حلّ لغات.نَکِرَنَکِرَ الْاَمْرَ یَنْکَرُ نَکَرًا ونُکْرًا وَنُکُوْرًا ونَکِیْرًا.جَھِلَہٗ اس سے بے خبر رہا.
Page 320
الرَّجُلَ لَمْ یَعْرِفْہُ اسے نہ پہچانا.(اقرب) اَوْجَسَ اِیْـجَاسًا اَحَسَّ وَاضْمَرَ.محسوس کیا.اور اپنے دل میں پوشیدہ رکھا.(اقرب) اَلْـخِیْفَۃُ مَصْدَرُ خَافَ.خَافَ کا مصدر ہے.جس کے معنی ہیں اَلْفَزَعُ گھبراہٹ اَلْـحَذَرُ.احتیاط کی بات.ضِدُّ الْاَمْنِ.امن کے خلاف حالت یعنی خطرہ.ڈر.(اقرب) تفسیر.حضرت ابراہیم کو کس بات کا خوف ہوا تھا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے ڈر گئے.بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے دل میں یہ خوف پیدا ہو اکہ شائد کوئی امر مہمان نوازی کے خلاف ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں کھاتے.مگر انہوں نے اس خوف کا اظہار نہ کیا کیونکہ مہمان کو یہ کہنا کہ شاید مہمان نوازی میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اس سے مہمان کی شرافت پر حرف آتا ہے کیونکہ اس سے اشارہ ٹپکتا ہے کہ وہ لالچی یا حریص ہے.حضرت ابراہیم نے کس بات کو نہیں سمجھا اور یہ جو فرمایا کہ انہیں پہچانا نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے تو حضرت ابراہیم ان کو معمولی مسافر سمجھتے تھے لیکن جب دیکھا کہ یہ کھانا نہیں کھاتے تو خیال کیا کہ غالباً میں نے ان کے یہاں آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا.کیونکہ اگر عام مسافر ہوتے تو مہمان نوازی کو قبول کرتے کہ ان بیابانی علاقوں میں مسافر بلامہمان نوازی کے گزارہ ہی نہیں کرسکتے.ان لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم کے چہرہ سے پہچان لیا کہ یہ حیران ہیں کہ کیا مہمان نوازی میں کوئی نقص ہو گیا ہے.یا ان لوگوں کے یہاں آنے کا کوئی اور مقصد ہے اس لئے انہوں نے تسلی دینے کے لئے کہہ دیا کہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں بلکہ ہم ایک عذاب کی خبر لے جارہے ہیں اس وجہ سے کھانا نہیں کھا سکتے.بشارت لانے والوں کے انسان ہونے پر ایک اور دلیل اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ فرشتے نہ تھے کیونکہ اگر فرشتے ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ ہم چونکہ لوطؑ کی قوم کی طرف جارہے ہیں اس لئے کھانا نہیں کھا سکتے.بلکہ یہ کہتے کہ ہم تو فرشتے ہیں کبھی کھانا کھایا ہی نہیں کرتے.
Page 321
وَ امْرَاَتُهٗ قَآىِٕمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ١ۙ وَ مِنْ اور اس کی بیوی (بھی پاس ہی) کھڑی تھی اس پر وہ گھبرائی تب ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحٰق کے بعد یعقوب وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ۰۰۷۲ (کی پیدائش) کی بشارت دی.حلّ لُغات.ضَحِکَ ضَـحِکَ یَضْحَکُ، ضَحْکًا وَضِحْکًا وضِحِکًا وَضَحِکًا.ضِدُّ بَکٰی.رونے کی مخالف حالت کا یعنی ہنسنے کا نام ضـحک ہے.ضَـحِکَ الرَّجُلُ ضَـحَکًا عَـجِبَ اَوْفَزِعَ.اس نے تعجب کیا یا گھبرا گیا.(اقرب) ضَـحِکَ فَزِعَ.وَبِہٖ فَسَّرَ الْفَرَّاءُ الاٰیۃ.ضَحِکَ کے معنی گھبرا جانے کے بھی ہوتے ہیں.اور فرّاء نے اس آیت میں یہی معنی کئے ہیں.(تاج) وَیُسْتَعْمَلُ فِی السُّرُوْرِ الْمُجَرَّدِ نَحْوُ مُسْفِرَۃٌ ضَاحِکَۃٌ کبھی صرف خوشی کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے مُسْفِرَةٌ.ضَاحِكَةٌ وَاسْتُعْمِلَ لِلتَّعَجُّبِ الْمُجَرَّدِ تَارَۃً اور کبھی صرف تعجب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.(مفردات) تفسیر.حضرت ابراہیم ؑکی بیوی کی گھبراہٹ کا باعث حضرت ابراہیمؑ کی بیوی سن رہی تھیں انہوں نے یہ بات سنی تو گھبرا گئیں.اور ایک قوم کی تباہی پر دل میں درد پیدا ہوا.حضرت ابراہیمؑ کی بیوی کو بشارت دئیے جانے کا باعث اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی اور اسحٰق ؑ کی خبر کے ساتھ جو پہلے ان نیک لوگوں کے ذریعہ سے بھی مل چکی تھی حضرت یعقوبؑ کی پیدائش کی بھی خبر دی.جس کا یہ مطلب تھا کہ چونکہ بنی نوع انسان پر انہیں رحم آیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایک ترقی کرنے والی نسل دے گا.خدا تعالیٰ کا رحم کس قدر وسیع ہے.وہ عذاب میں گرفتار ہونے والوں سے سچی ہمدردی کو بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے.ذبیح کون تھا یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ذبیح کون تھا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ اسحاق ذبیح تھا.مسلمان کہتے ہیں کہ اسماعیلؑ ذبیح تھا.ان کی بحث تو خیر تاریخ سے تعلق رکھتی ہے.مگر بعض مسلمان بھی غلطی سے حضرت اسحاق کو ذبیح قرار دیتے ہیں.ان لوگوں کی غلطی اس آیت سے دور ہو جاتی ہے کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اسحاق ؑ کی پیدائش سے بھی پہلے خبر دےدی تھی کہ اسحاق ؑکے ہاں اولاد بھی
Page 322
ہوگی اور ان کا ایک بیٹا یعقوب مقرب الٰہی ہوگا.اور جس کی نسبت پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہو کہ وہ زندہ رہے گا بڑا ہوکر شادی کرے گا اور اس کا بیٹا پیدا ہوگا جو مقرب الٰہی ہوگا اس کی نسبت کب یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہو.اور پھر اس حکم سے دھوکا بھی لگ گیا ہو.اگر حضرت اسحاق ؑ کے متعلق ذبح ہونے کی رؤیا ہوتی تو کیا حضرت ابراہیمؑ دریافت نہ کرتے کہ الٰہی تو نے تو اس کے جوان ہونے اور ایک مقرب بارگاہ بچہ کے باپ ہونے کی خبر دی تھی اب اس کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے.کیا اس حکم کا مطلب کچھ اور تو نہیں.غرض اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہی تھے.اور کوئی وجہ نہیں کہ یہودیوں کی محرف مبدل کتب سے ڈر کر ہم حضرت اسحاق ؑ کو ذبیح قرار دینے کی کوشش کریں.قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَ اَنَا عَجُوْزٌ وَّ هٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا١ؕ اِنَّ اس نے کہا ہائے میری رسوائی کیا میں (بچہ) جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی (ہو چکی) ہوں اور یہ میرا خاوند بڑھاپے کی هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ۰۰۷۳ حالت میں ہے یہ (بات) یقیناً یقیناً ایک اچھنبی بات ہے.حلّ لُغَات.وَیْلَتٰی اصل میں وَیْلَتِیْ ہے یعنی اے میری وَیْلَۃِ اور وَیْلَۃ کے معنی ہیں اَلْفَضِیْحَۃُ.بدنامی اَلْبَلِیَّۃُ.مصیبت (اقرب) یہ کلمہ اصل میں مصیبت کے لئے استعمال ہوتا تھا.لیکن آہستہ آہستہ تعجب کے لئے استعمال ہونے لگا.اَلْعَجُوْزُ.اَلْمَرْءَ ۃُ الْمُسِنَّۃُ.بڑھیا عورت لِعَجْزِھَا عَنْ اَکْثَرِ الْاُمُوْرِ.یعنی بڑھیاعورت کو عَـجُوْز اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اکثر کاموں سے عاجز آجاتی ہے.وَھُوَ وَصْفٌ خَاصٌّ لَھَا.اور یہ لفظ بوڑھی عورت کے سواء اور کسی کے لئے استعمال نہیں ہوتا.(اقرب) اَلْبَعْلُ.رَبُّ الشَّیْءِ چیز کا مالک یَقُوْلُوْنَ مَنْ بَعْلُ ھٰذِہِ النَّاقَۃِ اَیْ رَبُّھَا کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کا بَعْل یعنی مالک کون ہے.اَلزَّوْجُ بعل کے معنی جوڑے کے بھی ہیں.وَ إلْمَرْأَۃُ بَعْلٌ وَبَعْلَۃٌ عورت کے لئے بھی یہ لفظ جوڑے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.اور اس وقت اس کے ساتھ تاء تانیث کا لانا اور نہ لانا دونوں باتیں جائز ہوتی ہیں.جیسے زَوْ جٌ اور زَوْجَۃٌ.(اقرب) تفسیر.حضرت ابراہیم ؑکی بیوی کا تعجب انکاری نہیں تھا اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الٰہی خبر کا انکار کررہی تھیں.ایک عام طبقہ کی مومنہ کے متعلق بھی یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انکار
Page 323
کے رنگ میں تعجب کرے گی.تو ایک نبی کی مومنہ بیوی کے متعلق کس طرح خیال ہوسکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھنے کے بعد اس کی قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب کرے؟ پس ان کا تعجب نعمت کی عظمت کے اظہار کے لئے تھا.حضرت ابراہیم ؑکا اپنا تعجب چنانچہ حضرت ابراہیم کے متعلق بھی ایک جگہ اس قسم کے لفظ آتے ہیں.اور وہ خود ہی تشریح بھی کردیتے ہیں.کہ میرا تعجب نعمت کی عظمت کے اظہار کے لئے ہے.نہ کہ اس کے ناممکن ہونے کے خیال سے فرمایااَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰۤى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ.قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ.قَالَ وَ مَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖۤ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ.(الحجر :۵۵ تا ۵۷) یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے باوجود میرے بوڑھا ہوجانے کے مجھے یہ خوشخبری دی ہے.تم کیسی عجیب خبر دیتے ہو! خبر دینے والوں نے کہا کہ ہم نے تجھے ایک یقیناً پوری ہوکر رہنے والی خبر دی ہے.پس تو مایوس نہ ہو.حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا کہ میں مایوس نہیں.خدا کی رحمت سے تو گمراہ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں.اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ایسے ہی لفظ حضرت ابراہیمؑ نے کہے ہیں اور پھر خود تشریح بھی کردی ہے کہ میرا تعجب مایوسانہ تعجب نہیں بلکہ عظمت نعمت کے اظہار کے طور پر ہے.قَالُوْۤا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَ بَرَكٰتُهٗ انہوں نے کہا کیا تو اللہ (تعالیٰ) کی بات پر تعجب کرتی ہے.اے اس گھر والو تم پر( تو) اللہ (تعالیٰ) کی رحمت اور عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ١ؕ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۰۰۷۴ اس کی ہر (قسم کی) برکات (نازل ہو رہی) ہیں (پس یہ کوئی اچنبی بات نہیں) وہ یقیناً بہت ہی تعریف والا (اور) بزرگ شان والا ہے.تفسیر.شیعہ اہل بیت میں بیویوں کو شامل نہیں کرتے(تفسیر القمّی زیر آیت لیذھب عنکم الرجس اہل البیت.الاحزاب:۳۴).مگر یہاں صرف بیوی کو ہی اہل بیت کہا ہے.حالانکہ ابھی تک ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی.حق یہی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اہل بیت کا لفظ آیا ہے وہاں بیوی بھی شامل ہے.
Page 324
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَ جَآءَتْهُ الْبُشْرٰى پس جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوگئی اور اسے خوشخبری ملی تو( اس وقت) وہ لوط کی قوم کے متعلق ہمارے يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍؕ۰۰۷۵ ساتھ بہت جھگڑتا تھا.حلّ لُغات.رَوْعٌ.اَلرَّوْعُ.الْفَزَعُ.گھبراہٹ رَاعَ فَزِعَ.گھبرایا.(اقرب) تفسیر.حضرت ابراہیم کا یہ خوف قوم لوط کے متعلق تھا یہ خوف حضرت ابراہیمؑ کا اپنے متعلق نہیں تھا کہ اس کو محل اعتراض قرار دیا جائے بلکہ قوم لوط کے متعلق تھا اور یہ تقویٰ کے عین مطابق اور اعلیٰ اخلاق میں سے ہوتا ہے.پہلے تو حضرت ابراہیمؑ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ حیران رہ گئے کہ میں اب کروں تو کیا کروں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو ایک بہتر قوم مل جائے گی تو ان کے غم کا بوجھ کم ہوا.اور محبت الٰہی کا نظارہ دیکھ کر لوط کی قوم کے بارہ میں بھی درخواست کرنی شروع کی.اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ۰۰۷۶ ابراہیم یقیناً یقیناً بردبار دردمند(دل رکھنے والا اور ہمارے حضور) بار بار جھکنے والا تھا.حل لغات.اَوَّاہٌ اَ لْاَوَّاہُ کَثِیْرُ التَّأَوُّہِ اِشْفَاقًا وَفَرَقًا جو خوف اور محبت کی وجہ سے بہت آہیں بھرتا ہو.(اقرب) مُنِیْبٌ اَنَابَ اِلَیْہِ.رَجَعَ اِلَیْہِ.مَرَّۃً بَعْدَ مَرَّۃٍ.بار بار رجوع کیا.پس منیب کے معنی ہوئے بار بار رجوع کرنے والا.(اقرب)
Page 325
يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا١ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ١ۚ (اس پر ہم نے اسے کہا) اے ابراہیم تو اس (دعا) سے اپنا رخ پھیر لے.اب تو تیرے رب کا حکم یقیناً آچکا ہے اور وَ اِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ۰۰۷۷ ان کی یقیناً یہ حالت ہے کہ ان پر ہٹایا نہ جاسکنے والا عذاب آرہا ہے.تفسیر.اللہ تعالیٰ کی محبت حضرت ابراہیم ؑسے اللہ تعالیٰ کی محبت حضرت ابراہیمؑ سے کتنی بڑھی ہوئی تھی.انہیں یہ نہیں کہا کہ میں تیری بات نہیں سنتا.بلکہ یہ فرمایا کہ اے ابراہیم! یہ سوال جانے ہی دو.تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے.اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان پر عذاب آئے گا.اس لئے اصرار نہ کرو.وَ لَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ اور جب ہمارے فرستادے لوط کے پاس آئے تو ان کی وجہ سے اسے غم ہوا اور وہ بے بس ہو گیا ذَرْعًا وَّ قَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ۰۰۷۸ اور کہا یہ دن (بہت) سخت (چڑھا) ہے.حلّ لُغَات.سَاءَ ہٗ.سَاءَہٗ فَعَلَ بِہٖ مَایَکْرَھُہٗ.اَوْ اَحْزَنَہٗ.اس سے ایسا سلوک کیا جو اسے ناپسند ہے.یا یہ کہ اسے غمگین کیا.سِیْٓءَ بِہِ فُعِلَ بِہٖ الْمَکْرُوْہُ اس سے ناپسند معاملہ کیا گیا.(اقرب) ضَاقَ بِہٖ ذَرْعًا.ضَعُفَتْ طَاقَتُہٗ وَلَمْ یَجِدْ مِنَ الْمَکْرُوْہِ فِیْہِ مَخْلَصًا اس کی طاقت کمزور ثابت ہوئی اور ناپسندیدہ بات سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ ملا.وَاَصْلُ الذَّرْعِ بَسْطُ الْیَدِ فَکَاَنَّکَ تُرِیْدُ مَدَدْتُ یَدَیَّ اِلَیْہِ فَلَمْ تَنَلْہُ اور ذَرْعٌ کے اصل معنی ہاتھ پھیلانے یا بڑھانے کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا.مگر میں اسے پکڑ نہ سکا وَاَرَادَ بِالذِّرَاعِ فِی قَوْلِہٖ ع ’’وَلٰکِنْ کَانَ اَرْحَبَھُمْ ذِرَاعًا‘‘.اَلنَّفْسُ.اور مذکورہ بالا مصراع میں ذراع سے مراد نفس ہے.(اقرب) یَوْمٌ عَصِیْبٌ شَدِیْدٌ الْحَرِّ اَوْ شَدِیْدٌ.یَوْمٌ عَصِیْبٌ کے معنی سخت گرم دن کے یا سخت دن کے ہیں.(اقرب)
Page 326
تفسیر.حضرت لوط ؑ کی تکلیف کا باعث مہمانوں کا بن بلائے آجانا نہ تھا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگ حضرت لوط ؑ کے پاس آئے تو انہیں ان سے بہت تکلیف ہوئی.اور انہوں نے ان کے فعل سے مخلصی کی کوئی صورت نہ پائی.یا انہیں مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے بہت دقت پیش آئی.مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول جن کا ذکر ہے جب حضرت لوط کے پاس مہمان آکر ٹھہرے اور باوجود حضرت لوط ؑ کے ٹلانے کے نہ ٹلے اور بن بلائے مہمان بنے رہے تو اس سے حضرت لوطؑ کے دل کو تکلیف ہوئی.اور اسی تکلیف کا اس جگہ ذکر ہےمگر یہ بات غلط ہے.اس واقعہ کی حقیقت بائیبل کی روشنی میں میرے نزدیک بائیبل میں جو واقعہ لکھا ہے وہ صحیح ہے اور اسی کی طرف اس جگہ اشارہ ہے اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ حضرت لوط ؑ کی بستی کے پاس پہنچے تو حضرت لوطؑ نے ان لوگوں کو اپنے گھر چلنے کی دعوت دی.انہوں نے اس سے انکار کیا.غالباً اس امر سے ڈرے ہوں گے کہ انہیں تکلیف ہوگی.مگر حضرت لوط ؑ نے اصرار کیا.انہوں نے انکار پر اصرار کیا.اس پر حضرت لوط کو تکلیف ہوئی.اور اسی تکلیف کا اس جگہ ذکر ہے اور خدا کا اپنے نبی کی مہمان نوازی کی شان بتانا مقصود ہے.نہ اس کے بخل اور بدخلقی کا اظہار.(دیکھو پیدائش باب۱۹) وَ جَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ١ؕ وَ مِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ اور اس کی قوم( غصہ سے) اس کی طرف بھاگتی کانپتی ہوئی اس کے پاس آئی اور (اس سے) پہلے (بھی) وہ( لوگ السَّيِّاٰتِ١ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ نہایت خطرناک) بدیاں کیا کرتے تھے.اس نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں (تمہارے ہی گھروں میں بیاہی فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ لَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ١ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ ہوئی) ہیں وہ تمہارے( اور تمہاری آبرو کے) حق میں نہایت پاک( دل اور پاک خیال) ہیں.پس تم اللہ کا
Page 327
رَّشِيْدٌ۰۰۷۹ تقویٰ اختیار کرو اور میرے مہمانوں (کی موجودگی) میں مجھے رسوا نہ کرو.کیا تم میں سے کوئی( بھی) سمجھ دار( آدمی) نہیں ہے.حلّ لُغَات.اُھْرِعَ اُھْرِعَ الرَّجُلُ (مَجْہُوْلًا) أُرْعِدَ مِنْ غَضَبٍ اَوْضُعْفٍ اَوْخَوْفٍ اَوْبَرْدٍ.خوف سردی غضب یا ضعف سے کانپنے لگا.اُعْـجِلَ عَلَی الْاِسْرَاعِ فَھُوَ مُھْرَعٌ.اسے تیزی سے دوڑایا گیا.ایسے شخص کو مُھْرَعٌ کہیں گے وَفِی اللِّسَانِ اَلْھَرَعُ وَالْھُرَاعُ وَالْاِھْرَاعُ شِدَّۃُ السَّوْقِ اور لسان العرب میں ہے کہ اِھْرَاعٌ کے معنی تیز چلانے اور زور سے ہانکنے کے ہوتے ہیں.قَالَ اَ بُوْعُبَیْدٍ اُھْرِعَ الرَّجُلُ.اِذَا اَ تَاکَ وَھُوَ یُرْعَدُ مِنَ الْبَرْدِ.ابوعبید کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص سردی سے کانپتا ہوا آئے تو اس کی نسبت اُھْرِعَ کا لفظ استعمال کرتے ہیں.اَقْبَلَ الشَّیْخُ یُھْرَعُ اَیْ اَقْبَلَ یُسْرِعُ مُضْطَرِبًا.یعنی بڈھا گرتا پڑتا دوڑتا ہوا آیا.(اقرب) تفسیر.حضرت لوط ؑ کو اپنی قوم کی طرف سے بدکاری کا خطرہ نہیں تھا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے افعال بد کی وجہ سے حضرت لوط ؑ کے دل میں خطرہ پیدا ہوا کہ وہ کوئی شرارت نہ کریں اس سے کوئی خاص شرارت مراد نہیں چونکہ وہ پہلے بھی شرارتیں کیا کرتے تھے.اس لئے حضرت لوط ؑ کو خطرہ ہوا.مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے.وہ لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوئے اور ان سے بدی کرنے کو دوڑ آئے.مگر میرے نزدیک مفسرین کا یہ خیال غلط ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ حجر ع۵ میں فرماتا ہے اَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ(الحجر:۷۱).یعنی کیا ہم نے تم کو غیر علاقہ کے آدمی لانے سے روکا ہوا نہیں ہے.اگر وہ کسی بدکاری کا ارادہ رکھتے تھے اور ان لوگوں کے آنے پر خوش تھے تو چاہیےتھا کہ تاکید کرتے کہ روز مسافروں کو پکڑ کر شہر میں لایا کرو.مگر وہ لوگ تو ناراض ہوکر کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تم کو پہلے سے روکا ہوا نہیں ہے کہ غیر علاقہ کے آدمی کو شہر میں مت لایا کرو؟ اگر کہا جائے کہ دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ جَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ۠.(الحجر:۶۸) کہ شہر والے خوش ہوکر بھاگے آئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس خوشی سے بھی یہ مراد نہیں کہ ان مہمانوں سے کسی قسم کی بے حیائی کا فعل کریں گے بلکہ خوشی کا سبب یہ تھا کہ آج لوط ؑ کو سزا دینے کا بہانہ مل گیا ہے اور وہ ہمارے قابو چڑھ گیا ہے.حضرت لوط ؑ کا تعلق شہری حکومت سے تھا اصل بات یہ ہے کہ پرانے زمانہ میں عام طور پر الگ الگ
Page 328
شہروں کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں.اور یہ علاقہ جس میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوط ؑ رہتے تھے یہ تو اس وقت باقاعدہ حکومتوں سے بالکل خالی تھا.ہر شہر یا قصبہ یا چند قصبات کی اپنی الگ حکومت ہوتی تھی جوجمہوریت کا رنگ رکھتی تھی کبھی کوئی ملک حاکم ہوتا تھا کبھی صرف شہر کے رؤسا مل کر امور سیاسیہ کو طے کرلیا کرتے تھے.سڈوم اور عمورا دونوں بستیاں جن سے حضرت لوط ؑ کا تعلق تھا ایسی ہی شہری حکومتوں میں سے تھیں اور شہر کا ملک ہی ان کا بادشاہ ہوتا تھا.(دیکھو پیدائش باب۱۴) اس بستی کے مالک باشندوں کی ارد گرد کی بستیوں سے پرخاش تھی طالمود جو یہود کی روایات اور تاریخ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ ان بستیوں کے لوگ مسافروں کو لوٹ لینے کے عادی تھے.(دیکھو جیوش انسائیکلوپیڈیازیر لفظ سڈوم) اور جو قوم ہمسایوں کو اس طرح دکھ دے گی وہ ان سے خائف بھی رہے گی.کہ وہ بھی کسی وقت اسے نقصان نہ پہنچائیں.اور سڈوم والوں سے تو ہمسایوں کی عملاً بھی لڑائی رہتی تھی.(دیکھو پیدائش باب ۱۴ آیت۲) اس سبب سے یہ لوگ غیرمعروف آدمیوں کو شہر میں آنے نہیں دیتے تھے.تاکہ ایسا نہ ہو کہ رات کو شہر کے دروازے کھول دیں اور دشمن سوتے میں آکر حملہ کر دیں.حضرت لوط ؑ چونکہ سنت انبیاء کے مطابق مہمان نواز تھے وہ مسافروں کو لے آئے کہ باہر رہیں گے تو لوٹے جائیں گے.یہ لوگ ان کو منع کرتے.جیسا کہ سورہ حجر کی مذکورہ بالا آیت سے ثابت ہے.حضرت لوط ؑ کی قوم کا ایک ہی وقت میں غصہ بھی اور خوشی بھی اس دفعہ جب پھر حضرت لوط ؑ آنے والے رسولوں کو لے آئے تو یہ لوگ ایک طرف تو غصہ سے بھر گئے کہ ہماری ہدایت کے خلاف یہ اجنبیوں کو لے آئے ہیں اور دوسری طرف خوش بھی ہوئے کہ اب لوط ؑ کو پکڑنے کا بہانہ مل جائے گا.اور یہ قصہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا.حضرت لوط ؑکے جواب میں بیٹیوں کا ذکر جب یہ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط ؑ کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ پہلے بھی مجھے مہمان لانے سے روکتے رہے ہیں اس لئے وہ اس پہلے سلوک کی وجہ سے جو وہ لوگ ان سے کیا کرتے تھے ڈرے کہ کہیں مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کریں.اور ان لوگوں سے کہا کہ میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں (ان کی دو بیٹیوں کی اس شہر کے دو آدمیوں سے شادی ہوچکی تھی) وہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزگی کا موجب ہیں.یعنی مہمانوں کو رسوا کرکے نکالو گے تو اس میں تمہاری بدنامی ہے.تم کو خوف ہے کہ باہر کے لوگوں سے مل کر میں تم کو نقصان نہ پہنچاؤں تو میری بیٹیاں تمہارے اپنے گھروں میں موجود ہیں.تم ان کو سزا
Page 329
دے کر مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو.اس طرح تمہاری بدنامی بھی نہ ہوگی.حضرت لوط ؑنے بدکاری کے لئے اپنی لڑکیوں کا نہیں ذکرکیا تھا بعض لوگوں نے تورات کی اتباع میں اس آیت کے یہ معنی کئے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی باکرہ لڑکیوں کو (یا تو ان کی دو لڑکیاں کنواری ہی تھیں اور یا بیاہی ہوئی ابھی رخصت نہ ہوئی تھیں) ان لوگوں پر پیش کیا کہ ان سے بدکاری کرلو.لیکن مہمانوں سے کچھ نہ کہو (تفسیر فتح البیان زیر آیت ھذا) مگر یہ معنی نبی کی شان کے خلاف ہیں.وہ سب لوگوں سے زیادہ باغیرت ہوتے ہیں.ایسا کام جسے ادنیٰ سے ادنیٰ لوگ بھی نہیں کرسکتے وہ کیوں کرنے لگے؟ ایسے مقابلہ کے وقت میں تو بدکار لوگ بھی کبھی یہ تجویز پیش نہیں کرسکتے.پس یہ غلطی ان سے تورات کی نقل کی وجہ سے ہوئی ہے.قرآن کریم میں بدکاری کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا.حضرت لوط ؑ نے لڑکیوں کا ذکر دشمنی کے شبہ کے ازالہ کے لئے کیا تھا انہوں نے صرف شہر والوں کے خوف کو اس طرح دور کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ جب میرے عیال تمہارے قبضہ میں ہیں تو تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیےکہ میں تمہارا دشمن ہوں.اور دوسرے لوگوں سے مل کر تمہارے شہر کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا.اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو اس پر عمل کرنا تمہاری عزت کے قیام کے لئے اچھا ہوگا اور مہمانوں کو ذلیل کرنے کے عیب سے محفوظ ہوجاؤگے.شادی کرنے کے لئے لڑکیاں پیش کرنے کا خیال بھی صحیح نہیں بعض مفسرین قرآن یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے نکاح کے لئے لڑکیاں پیش کی تھیں(تفسیر فتح البیان زیر آیت ھٰذا).یہ خیال بھی درست نہیں معلوم ہوتا.کیونکہ بائیبل کے رو سے تو ان کی لڑکیاں بیاہی ہوئی تھیں.اگر باکرہ لڑکیاں نکاح شدہ لڑکیوں کے علاوہ بھی سمجھی جائیں تب بھی یہ عقل کے خلاف ہے کہ شہر کے لوگ تو ایک خاص قسم کے فحش کے لئے آئے ہوں اور حضرت لوط ؑ یہ کہیں کہ تم میں سے دو آدمی میری لڑکیوں سے بیاہ کرلیں.بیٹیوں سے مراد قوم لوط کی اپنی بیویاں بھی ہوسکتی ہیں یہ مراد بھی ہوسکتی ہے کہ حضرت لوط ؑ بیٹیاں ان لوگوں کی بیویوں کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں (یعنی تمہاری بیویاں) جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں ان سے تعلق تمہارے لئے بہت پاکیزہ امر ہے.اسے چھوڑ کر تم کن بدکاریوں میں مبتلا ہورہے ہو.گویا حضرت لوط ؑ چونکہ معمر ہوچکے تھے عام محاورہ کے مطابق ان لوگوں کی بیویوں کو اپنی بیٹیاں قرار دیتے ہیں.
Page 330
قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ١ۚ وَ اِنَّكَ انہوں نے کہا تو یقیناً یقیناً معلوم کر چکا (ہوا) ہے کہ تیری لڑکیوں کے متعلق ہمیں کوئی بھی حق (حاصل) نہیں ہے.لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ۰۰۸۰ اور جو (کچھ) ہم چاہتے ہیں اسے تو یقیناًیقیناً جانتا ہے.تفسیر.حضرت لوط ؑ نے جو ان لوگوں سے کہا کہ میری بیٹیاں تمہارے قبضہ میں ہیں اگر تم مجھ سے کوئی امر اپنے ملکی مصالح کے خلاف دیکھو تو ان کے ذریعہ سے مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہو چونکہ یہ ایک رنگ یرغمال کا تھا اور یرغمال کے متعلق یہ دستور تھا کہ اس میں نرینہ اولاد ہی رکھی جاتی تھی ان لوگوں نے جواب دیا کہ لڑکیاں رکھنے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے.اور تجھے معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں.یعنی تجھے معلوم ہے کہ ہم بہرحال مہمانوں کی آمد کو روکنا چاہتے ہیں.پس یہ کہنا کہ یرغمال رکھ لو اور مہمانوں کے متعلق مجھے کچھ نہ کہو ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جسے ہم تسلیم نہیں کرسکتے.مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ سے یرغمال کے خیال کی تائید جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت لوط ؑ نے لڑکیوں کو بدکاری یا نکاح کے لئے پیش کیا تھا اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ضرور ایسا ہی ہوگا.تبھی تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ لڑکیوں کے متعلق ہمارا کوئی حق نہیں.حالانکہ یہ آیت تو ان کے خلاف ہے.کیونکہ جو قوم بدکاری میں اس قدر بڑھ چکی ہو وہ شہوانی امور کے متعلق حق و ناحق کا سوال کب اٹھا سکتی ہے؟ ان کا یہ کہنا کہ ہمارا کوئی حق نہیں تو بتاتا ہے کہ یہاں یرغمال کا ہی سوال تھا اور چونکہ ان کے ہاں رواج تھا کہ یرغمال کے طور پر نرینہ اولاد ہی رکھی جاتی تھی وہ اسے خلاف دستور قرار دیتے ہیں اور بے فائدہ سمجھتے ہیں.قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ۰۰۸۱ اس نے کہا کاش مجھے تمہارے مقابلہ میں (کسی قسم کی) قوۃ( حاصل) ہو تی (تو میں تم کو تمہاری بدی سے روکتا) یا (پھر یہ علاج ہے کہ) میں ایک قوی ذریعہ حفاظت (یعنی خدا) کی پناہ لے لوں.حلّ لُغَات.رُکْنٌ الرُّکْنُ اَلْـجَانِبُ الْاَقْوٰی نہایت مضبوط یا سب سے مضبوط جانب.اَلْاَمْرُ الْعَظِیْمُ
Page 331
عظمت اور بڑائی والی بات.مَایُقْوٰی بِہٖ مِنْ مِلْکٍ وَ جُنْدٍ وَغَیْرِہِ.قوۃ کا ذریعہ اور سامان خواہ جائیداد ہو یا جتھاوغیرہ.اَلْعِزُّ وَالمَنَعَۃُ.غلبہ اور مددگاروں اور حفاظت کرنے والوں کا جتھا.(اقرب) تفسیر.حدیث میں ہے عَنْ اَبِی ھُرَیْرَۃَ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحْمَۃُاللہِ اَوْ رَحِمَ اللہُ عَلٰی لُوْطٍ لَقَدْ کَانَ یأوِیْ اِلٰی رُکْنٍ شَدِیْدٍ (یَعْنِی اللہَ تَعَالیٰ عَزَّوَجَلَّ) ابوہریرہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمتیں ہوں حضرت لوط علیہ السلام پر یا یہ فرمایا کہ اس پر اللہ رحم کرے وہ بار بار ایک رکن شدید کی پناہ لیتے تھے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے.(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا) حضرت لوط ؑ کا یہ مطلب ہے کہ اگر طاقت ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرکے بدی سے روکتا.مگر طاقت نہیں ہے.بس اب یہی ذریعہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈوں.اور تمہارے لئے عذاب طلب کروں.مگر میں ابھی دیر کرتا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ.لیکن جب اس دردمندانہ اپیل کی طرف بھی لوگوں نے توجہ نہ کی تو خدا تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اس قوم کی تباہی کی دعا کی.جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث سے ظاہر ہے.قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْۤا اِلَيْكَ فَاَسْرِ انہوں نے (یعنی مہمانوں نے )کہا اے لوط ہم یقیناًتیرے رب کے فرستادہ ہیں.وہ تجھ تک ہرگز نہیں پہنچیں گے بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَ لَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا (ان کی تباہی کا وقت آچکا ہے) اس لئے تُو رات کے کسی حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر تیزی سے (یہاں سے) امْرَاَتَكَ١ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ١ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی( فرد بھی) ادھر ادھر نہ دیکھے (اس طرح سے تم محفوظ رہو گے) سوائے تیری بیوی کے الصُّبْحُ١ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ۰۰۸۲ ( کہ) جو( عذاب) ان پر آیا (ہوا ہے )وہ اس پر بھی یقیناً آنے والا ہے.ان کا مقررہ وقت (آئندہ) صبح ہے (اور) کیا صبح قریب نہیں ہے.تفسیر.جب ان لوگوں نے حضرت لوط کی یہ بات سنی کہ وہ ان لوگوں کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور
Page 332
بددعا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس امر کو جسے اس وقت تک چھپائے رکھا تھا.ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے.ہم وہی بتانے آئے تھے.صرف تمہارے اہل عذاب سے بچائے جائیں گے.اور باقی شہر تباہ کیا جائے گا.اہل میں سے بھی بیوی نہیں بچ سکے گی.اور عذاب صبح کے وقت تک آجائے گا.فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا پھر جب ہمارا (عذاب کا) حکم آیا تو ہم نے اس( بستی) کے اوپر والے (حصہ) کو نیچے والا (حصہ )بنا دیا.اور اس پر حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ١ۙ۬ مَّنْضُوْدٍۙ۰۰۸۳ پتھروں کی یعنی تہ بہ تہ (کی ہوئی) کنکروں والی (سخت شدہ) مٹی کی بارش برسائی.حلّ لُغَات.سِـجِّیْلٌ السَّجِّیْلُ حـَجَرٌ وَطِیْنٌ.تہہ بتہہ مُخْتَلِطٌ.ایسا مجموعہ جس میں کنکر اور مٹی ملی ہوئی ہو.(مفردات) حِـجَارَۃٌ کالْمَدَرِ ڈھیلوں کی شکل کے پتھر.(اقرب) نَضَدَ نَضَدَ الْمَتَاعَ یَنْضِدُ نَضْدًا.جَعَلَ بَعْضَہٗ فَوْقَ بَعْضٍ.ایک دوسرے پر تہہ بتہہ لگا کر رکھا.(اقرب) پس مَنْضُوْدٌ کے معنی ہوئے تہہ بتہہ لگا کر رکھا ہوا.تفسیر.یہ عذاب غالباً شدید زلزلہ کی صورت میں آیا تھا معلوم ہوتا ہے شدید زلزلہ سے یہ قوم ہلاک ہوئی تھی.شدید زلزلوں میں زمین الٹ بھی جاتی ہے.اور اس کے ٹکڑے اڑ کر پھر وہیں آکر گرنے لگتے ہیں.نشان لگے ہوئے پتھروں سے مراد یہ ہے کہ ازل سے ان پتھروں کے لئے یہی مقدر تھا کہ اس قوم کی تباہی کا موجب بنیں.واقعہ لوط کے متعلق بعض امور ضروریہ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت لوط ؑ حضرت ابراہیم ؑ کے بھائی حاران کے بیٹے تھے اور اُور سے جو عراق کے علاقہ کا ایک قصبہ تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی ہجرت کرکے کنعان یعنی فلسطین کے ملک کی طرف چلے آئے تھے.یہاں پہنچ کر وہ حضرت ابراہیمؑ سے الگ ہوکر صدوم نامی بستی میں رہنے لگے(پیدائش باب ۱۳ و ۱۴).حضرت لوط ؑکے متعلق بائبل کےاور قرآن کریم کے بیانوں میں اختلاف قرآن کریم اور بائبل میں لوط علیہ السلام کے واقعہ میں کچھ اختلافات بھی ہیں.بائبل حضرت لوط کو لڑاکا اور حاسد بتاتی ہے(پیدائش
Page 333
باب ۱۳).اس کے برخلاف قرآن کریم انہیں نیک بتاتا ہے.بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں آنے والوں نے حضرت ابراہیم ؑ کا پیش کردہ کھانا کھایا(پیدا ئش ۱۸/۸).قرآن کریم اس کا منکر ہے.اور عجیب بات یہ ہے کہ بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین شخص جو آئے تھے ان میں سے ایک خود خدا تھا.اور دوسرے دو فرشتے تھے.مگر باوجود اس کے وہ یہ شہادت دیتی ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا.ہر اک عقلمند ان دونوں بیانوں میں سچے بیان کو خود معلوم کرسکتا ہے.بائبل بتاتی ہے کہ حضرت لوطؑ نے اپنی لڑکیوں کو بدکاری کے لئے پیش کیا تھا(پیدائش ۱۹/۸).قرآن کریم اس کے برخلاف انہیں بطور ضمانت پیش کرنے کا ذکر کرتا ہے.ان کے سوا اور بھی اختلاف ہیں.مثلاً بائبل کہتی ہے کہ حضرت لوط کی بیوی نمک کا کھمبا بن گئی تھی(پیدائش ۱۹/۲۶).قرآن کریم ایسی فضول باتوں سے بالکل پاک ہے.یہ چند مثالیں قرآن کریم اور بائبل کے بیانات میں اختلافات اور ان کی حقیقت بیان کرنے کے لئے کافی ہیں.مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ١ؕ وَ مَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍؒ۰۰۸۴ جو تیرے رب کی تقدیر میں (ان کے لئے ہی) نشاندار (اور نامزد) کئےہوئے تھے اور ان( محمد رسول اللہ کے زمانہ کے) ظالموں سے (بھی) یہ عذاب دور نہیں.حل لغات.اَلْمُسَوَّمَۃُ الْمُرْسَلَۃُ.آزاد چھوڑے ہوئے الْمُعْلَمُۃُ جن پر نشان لگایا ہوا ہو.تفسیر.اس آیت کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ قصہ نہیں ہے.بلکہ پیشگوئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے لئے بھی ایسے ہی عذاب مقدر ہیں اور لوط کی بستی کی طرح آپ کی قوم کے بعض مخالفوں کے لئے بھی نیست و نابود ہوجانا مقدر ہوچکا ہے.وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا١ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ اور مدین کی طرف (ہم نے) ان کے بھائی شعیب کو (نبی بنا کر بھیجا) اس نے( انہیں) کہا اے میری قوم تم اللہ کی مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ١ؕ وَ لَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَ عبادت کرواس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں اور ماپ اور تول کو کم نہ( کیا) کرو
Page 334
الْمِيْزَانَ اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ میں (اس وقت) یقیناً تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں اور( ساتھ ہی) میں یقیناً تمہاری نسبت عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ۰۰۸۵وَ يٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَ ایک تباہ کن دن کے عذاب سے ڈررہاہوں.اور اے میری قوم تم ماپ اور تول کو انصاف الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ کے ساتھ پورا (کیا) کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۰۰۸۶ اور فسادی بن کر زمین میں خرابی مت پھیلاؤ.حل لغات.اَلْمِکْیَالُ مَایُکَالُ بِہٖ.وہ پیمانہ (ظرف) جس سے کسی چیز کی مقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے.چیزوں کا وزن معلوم کرنے کے دو طریق ہیں.ایک برتن کے ذریعہ سے دوسرے بٹہ وغیرہ کے مقابلہ پر وزن کرنے سے.گویا ایک جگہ کے لحاظ سے اور ایک بوجھ کے ذریعہ سے.پرانے زمانہ میں جگہ کے لحاظ سے زیادہ لین دین کیا جاتا تھا.اور آج کل بوجھ کے لحاظ سے اندازہ کرنے کا زیادہ رواج ہے.گو اب بھی سیال چیزوں کا جگہ کے لحاظ سے اندازہ کرتے ہیں.مکیال ہر اس پیمانہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے دوسری چیز کا اندازہ کیا جائے.الْمِیْزَانُ.آلَۃُ ذَاتِ کَفَّتَیْنِ.یُوْزَنُ بِہَا الشَّیْءُ وَیُعْرَفُ مِقْدَارُہٗ مِنَ الثِّقَلِ یعنی میزان ایک آلہ ہوتا ہے.دو پلڑوں والا (یعنی ترازو) جس سے چیز کا وزن کیا جاتا ہے.اور اس چیز کی مقدار بوجھ کے لحاظ سے معلوم کی جاتی ہے.اَلْمِقْدَارُ.یعنی یہ لفظ مطلق مقدار کے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے.(اقرب) تفسیر.آسودہ حال کا فریب کرنا بدترین ہے اِنِّيْۤ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ.میں تم کو اچھی اور آسودہ حالت میں دیکھتا ہوں.یعنی ٹھگی کا موجب اگر فقر ہو تب بھی وہ بری چیز ہے لیکن مال دار آدمی فریب سے لوگوں کا مال لوٹے تو وہ اور بھی برا ہے.
Page 335
محیط کو یوم کی وصف بنانےکی وجہ اِنِّيْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ.اَحَاطَہٗ بِالشَّیْ ءِ.کے معنے میں بتاچکا ہوں کہ ہلاک کر دینے کے ہوتے ہیں.یوم کی صفت محیط کو مجازاً مبالغہ کے اظہار کے لئے بنایا ہے.جیسے کہتے ہیں نَـہَارُہُ صَائِمٌ اس کا دن روزہ دار ہے.مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دنوں کو کامل روزہ کی حالت میں گزارتا ہے.ا سی طرح عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ سے مراد یہ ہے کہ اس دن کا عذاب بالکل تباہ کر دینے والا ہوگا.يَوْمٍ مُّحِيْطٍ سے یہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ وہ دن ختم نہیں ہوگا.جب تک سب قوم کو تباہ نہ کرلے.مدین حضرت شعیب علیہ السلام مدین قوم کی طرف آئے تھے اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے.جو قتورہ کے پیٹ سے تھے.(قتورہ آپ کی تیسری بیوی تھی یعنی سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ) ان کا ذکر پیدائش باب ۱/۲۵ میں آتا ہے.پرانے زمانے کے اصول کے لحاظ سے کہ باپ کے نام پر اولاد بھی پکاری جاتی تھی.ان کی اولاد بھی ان کے نام کے لحاظ سے مدین کہلائی.یہ بھی ہوسکتا ہے کہ شروع میں وہ بنو مدین کہلاتے ہوں.پھر کثرتِ استعمال سے بنو کا لفظ اڑ گیا ہو اور خالی مدین رہ گیا ہو.اس قوم کے مرکزی شہر کا نام بھی مدین ہے.ممکن ہے کہ ابتداء میں یہ دُور مدین کہلاتا ہو.پھر کثرتِ استعمال سے مدین رہ گیا ہو.مدین شہر کا محل وقوع یہ شہر خلیج عقبہ کے پاس تھا.بحیرہ احمر جہاں ختم ہونے لگتا ہے وہاں اس کی دو شاخیں ہوجاتی ہیں.ایک مصر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے اور ایک عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے.جو شاخ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ جاتی ہے اس کو خلیج عقبہ کہتے ہیں اور یہ شہر خلیج عقبہ کے پاس عرب کی جانب سمندر کے بالکل قریب چھ سات میل کے فاصلہ پر ہے.بوجہ اتنا قریب ہونے کے پرانے زمانہ کے جغرافیہ نویسوں میں سے بعض اس کو بندرگاہ لکھتے ہیں اور بعض اس کو خشکی کا شہر لکھتے ہیں.عرب سے جو قافلے مصر کو جاتے تھے وہ مدین کے راستہ سے ہوکر جاتے تھے.اب بھی مدین نام کی کئی بستیاں چھوٹے چھوٹے قصبات کے رنگ میں ملتی ہیں.اصل مدین شہر اب موجود نہیں ہے.مدین کی اولاد حجاز کے شمال میں بستی تھی.اور یہ شہر انہی کا بنایا ہوا تھا.آنحضرت ؐ اور حضرت موسیٰ میں ایک وجہ مماثلت حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعۂ قتل کے بعد ہجرت کرکے مدین میں ہی آئے تھے(خروج ۲/۱۵).اور بنی اسرائیل کو لے کر بھی جب وہ آئے تب بھی وہ مدین ہی کے قریب آکر ٹھہرے تھے(خروج باب ۱۸).یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشابہت ہے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ٹھہرے اور موسیٰ علیہ السلام مدین میں ٹھہرے.گو مدینہ کا نام پہلے
Page 336
یثرب تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی وبائیں دور کرکے اس کا نام مدینہ ڈلوا دیا.اور اس طرح ظاہری مشابہت بھی قائم ہو گئی.حضرت شعیب ؑ کا زیادہ تر مقابلہ اہل شہر سے تھا قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیبؑ کا زیادہ مقابلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اہل شہر سے ہی تھا.سورۂ اعراف میں آتا ہے.قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا١ؕ قَالَ اَوَ لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ.(الاعراف:۸۹) یہ قوم تجارتی کاروبار میں خیانت کا شیوہ رکھتی تھی (۲) دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی قوم شرک میں مبتلا ہونے کے علاوہ معاملات کی خرابی کی مرض میں بھی مبتلا تھی.تبھی تو اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَ الْمِيْزَانَ.پیمانہ اور تول میں کمی نہ کیا کرو.اس قوم کی مالی حالت اچھی تھی (۳)اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی کیونکہ فرمایا ہے کہ اِنِّی اَرٰکُمْ بِخَیْرٍ یعنی میں یقیناً تمہاری مالی حالت اچھی دیکھتا ہوں.یہ قوم راہ زنی بھی کرتی تھی (۴)یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ڈاکے بھی ڈالتی تھی کیونکہ فرمایا ہے.وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا.(الاعراف :۸۶) وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.(ہود:۸۶) اور یہ الفاظ یا تو قتل و غارت پر دلالت کرتے ہیں یا ڈاکہ و راہ زنی پر.چونکہ یہ علاقہ عرب اور شام اور مصر کے راستوں پر تھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسافروں کو لوٹ لیا کرتےتھے.اس قیاس کو مزید تقویت اس امر سے حاصل ہوتی ہے کہ مدین قوم کے قبضہ میں مدین کے پاس ایک جنگل تھا جس میں ودان قوم رہتی تھی جو مدین کے بھتیجے اور حضرت ابراہیمؑ کے ایک دوسرے بیٹے کی نسل سے کہ وہ بھی قتورہ کے بطن سے تھا پوتے تھے.اس جنگل میں رہنے والوں کو قرآن کریم نے اصحاب الایکہ کے نام سے موسوم کیا ہے.اور سورۂ شعراء (رکوع ۱۰) میں ان اصحاب الایکہ کو بھی حضرت شعیب کی زبانی یہی کیا گیا ہے جو کہ مدین والوں کو کہا گیا ہے.چنانچہ فرمایاكَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ.اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ.اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ.فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ.وَ مَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ١ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ(الشعراء:۱۷۷ تا ۱۸۲).ایکہ عربی زبان میں ایسے جنگل کو کہتے ہیں کہ جس میں بیریاں اور پیلو کے درخت ہوں.ایسے جنگل میں ڈاکے ڈالنے زیادہ آسان ہوتے ہیں کیونکہ بیری اور پیلو کے پتے نیچے سے شروع ہوتے ہیں.جن کی وجہ سے ان کےپیچھے آدمی آسانی سے چھپ سکتا ہے اور
Page 337
سورۂ حجر (ع۵) میں فرماتا ہےوَ اِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ.فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ١ۘ وَ اِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ (الحجر:۷۹،۸۰).اور اصحاب ایکہ ضرور ظالم تھے.اس وجہ سے ہم نے انہیں ان کے جرم کی سزا دی اور وہ دونوں (قوم لوط اور اصحاب الایکہ) ایک عام چلنے والے راستہ پر واقع تھے.مفسرین کا قول ہے کہ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے اور ان کے خسر تھے.اور انہیں کے پاس موسیٰ ؑ واقعہ قتل کے بعد آکر ٹھہرے تھے.اور پھر ان کی لڑکی سے شادی کرلی تھی(تفسیر حقانی زیر آیت ھذا).لیکن تورات میں اس شخص کا نام جس کے پاس موسیٰ ؑآکر ٹھہرے اور جس کی لڑکی سے انہوں نے شادی کی تھی بعض جگہ حوباب اور بعض جگہ یترو آتا ہے(خروج ۳/۱ و گنتی ۱۰/۲۹).مصنف ارض القرآن کی بھی یہی رائے ہے کہ مفسرین کا قول صحیح ہے اور انہوں نے اس امر کے ثبوت میں کئی دلائل دیئے ہیں.چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ (۱)بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آئے تھے تو پہلے مدین میں آکر ٹھہرے تھے.اور جب مدین کی عورتوں نے انہیں لوٹنا شروع کیا اور ان کو شرک میں مبتلاء کرنے لگیں (کیونکہ وہ ان کو اپنے مندروں میں لے جاتی تھیں) تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر چڑھائی کی اور ساری کی ساری قوم کو تباہ کر دیا.حتیٰ کہ بچوں اور عورتوں کو بھی.(۲) دوسری دلیل وہ یہ د یتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت شعیبؑ کا قول نقل ہے.بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ (ہود:۸۷) اس سے مراد بھی یہی ہوسکتی ہے کہ حضرت موسیٰ ؑ نے اہل مدین کی زمین بنی اسرائیل میں بانٹ دی تھی.حضرت شعیب ؑ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا.جس قدر زمین تمہارے لئے چھوڑ دی ہے تم اس پر اکتفا کرو.لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا (الاعراف:۸۶) سے بھی ان کے نزدیک یہ ہی مراد ہے کہ بنی اسرائیل سے صلح کرنے کے بعد لڑو نہیں.(ارض القرآن از سید سلیمان ندوی زیر عنوان مدین ، شعیب) مصنف ارض القرآن نے مدین قوم کے مقام اور ان کے قومی حالات کے متعلق جو کچھ لکھا ہے میں اس سے متفق ہوں اور ان کی محنت کی داد دیتا ہوں.لیکن مجھے حضرت شعیب کی شخصیت کے متعلق ان سے اختلاف ہے.اور اس کے مندرجہ ذیل وجوہ ہیں: (۱) قرآن کریم میں حضرت شعیب کی قوم کا یہ قول درج ہےاَوْاَنْ نَّفْعَلَ فِيْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا (ھود:۸۸) کیا تو اس امر کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے اموال کو جس طرح چاہیں استعمال نہ کریں.
Page 338
لیکن نہ بائبل سے اور نہ قرآن کریم سے کسی ایسے واقعہ کا پتہ لگتا ہے جس کی بناء پر ہم اس آیت کو بنی اسرائیل اور اہل مدین کے تعلقات پر چسپاں کرسکیں.(۲) حضرت شعیبؑ کا قول ہے کہلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا (الاعراف:۸۶)زمین میں صلح قائم ہوجانے کے بعد فساد نہ کرو.لیکن حضرت موسیٰ کی قوم سے جو مدین والوں کا معاملہ ہوا تھا اس پر یہ فقرہ چسپاں نہیں ہوتا کیونکہ موسیٰ کی قوم سے ان کی کوئی صلح نہ ہوئی تھی.بلکہ برخلاف اس کے اگر بائبل کا بیان صحیح تسلیم کیا جائے تو انہوں نے مدین والوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرلیا تھا.پس صلح کا تو اس موقع پر کوئی ذکر ہی نہیں.یہاں تو فساد کی بنیاد پڑتی نظر آتی ہے.ان حالات میں ہم مجبور ہیں کہ اصلاح سے مراد وہ نیکی کی بنیاد لیں جو پہلے نبی کے زمانہ میں ڈالی گئی تھی.اور یہ سمجھیں کہ شعیب ؑ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ جو نیکی پہلے انبیاء کے ذریعہ سے قائم ہوئی تھی اسے تم لوگ اپنے اعمال سے برباد نہ کرو.(۳) تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حوباب مدین کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں انہیں زمین مل گئی(گنتی باب ۱۰).اور اس کے بعد ان کا ذکر خاموشی کے پردہ کے پیچھے چھپ جاتا ہے.لیکن یہ امر کہ ایک نبی اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک دوسرے علاقہ میں چلا گیا اور اپنی بعثت کے کام کو بھلا کر صرف زمیندارہ میں مشغول ہو گیا عقل کے خلاف ہے.(۴) بائبل میں حوباب کے نبی ہونے کا کہیں ذکر نہیں حالانکہ جب وہ حضرت موسیٰ ؑ کے زمانہ کے آدمی تھے اور پھر ان کے خسر تھے تو اگر وہ نبی ہوتے تو غالب خیال یہ ہے کہ ان کی نبوت کا ذکر اس میں ہوتا.(۵) قرآن کریم میں حضرت شعیب کا متعدد جگہ ذکر آیا ہے.اور اسی طرح حضرت موسیٰ ؑ کے خسر کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے.لیکن ایک جگہ بھی اس نے اشارہ نہیں کیا.کہ یہ دونوں وجود ایک ہی ہیں.اور نہ کہیں موسیٰ ؑ کے خسر کے نبی ہونے کا ذکر آیا ہے.(۶)یہ عقل کے خلاف ہے کہ ایک نبی کی قوم کو دوسرے نبی کے ہاتھوں سے تباہ کروایا جائے.اور پھر اگر یہ صحیح ہو تو لازماً شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو حضرت موسیٰ ؑ کا ساتھ دینا چاہیےتھا مگر اس کا ذکر تورات میں بالکل نہیں بلکہ یہ ذکر بھی نہیں کہ حوباب پر ایمان لانے والا کوئی ایک شخص بھی تھا.برخلاف اس کے وہاں یہ لکھا ہے کہ صرف حوباب کی اولاد ان کے ساتھ تھی(گنتی باب ۱۰).لیکن
Page 339
قرآن کریم بتاتا ہے کہ شعیب ؑ پر ایمان لانے والی ایک جماعت تھی.(۷) سب سے بڑھ کر اور قطعی ثبوت اس امر کا کہ شعیب اور حوباب الگ الگ شخص تھے یہ ہے کہ قرآن کریم میں حضرت شعیب کی قوم کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡىِٕهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا (الاعراف:۱۰۴) یعنی اس قوم کے بعد ہم نے موسیٰ کو مبعوث کیا تھا.پس جب قرآن کریم بوضاحت اور بنصِ صریح حضرت موسیٰ کی بعثت کو شعیب ؑ کی قوم کی تباہی کے بعد بتاتا ہے تو ہم کس طرح خیال کرسکتے ہیں کہ شعیب اور حوباب موسیٰ علیہ السلام کے خسر ایک ہی شخص تھے.اور یہ کہ شعیب کی قوم کی تباہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی.(۸) اگر شعیب کو حضرت موسیٰ ؑ کا خسر قرار دیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ موسیٰ کے مدین پہنچنے پر شعیب ؑ مبعوث ہوئے.اور ان کا کام صرف موسیٰ ؑ سے صلح رکھنے کی تلقین کرنا تھا.حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو اور قوموں سے بھی واسطہ پڑا.جیسے عمالقہ وغیرہ.لیکن انہیں سمجھانے کے لئے کوئی نبی مبعوث نہ ہوا.(۹) حضرت شعیب علیہ السلام کا قول اسی رکوع میں آتا ہے.لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْۤ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَاۤ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ١ؕ وَ مَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ (ھود:۹۰) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب حضرت لوط کی قوم کے قریب بعد میں ہوئے.پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں انہیں قرار دینا درست نہیں ہوسکتا.(۱۰) اگر شعیب ؑ حضرت موسیٰ ؑ کے خسر ہوتے تو جیسا انہوں نے نوح، ہود اور صالح کی قوم کی تباہیوں کا ذکر کیا تھا تو کیوں تازہ بتازہ تباہی جو حضرت موسیٰ کے دشمن فرعون کو پہنچی تھی اس کا ذکر نہ کرتے.خصوصاً جبکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تائید کررہے تھے.تو یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اس موقع پر ان تائیدات کا ذکر چھوڑ دیں گے.جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں ملیں.پس میرے نزدیک ان مفسرین کا خیال غلط ہے جو شعیب ؑ کو حضرت موسیٰ ؑ کا خسر قرار دیتے ہیں.حوباب جو حضرت موسیٰ ؑ کا خسر تھا وہ بالکل اور شخص ہے اور حضرت شعیب ؑ اور شخص ہیں.اور میرے نزدیک یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تباہ ہوچکی تھی.اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں صرف اس کی نسل کا بقیہ موجود تھا اور شان و شوکت اس قوم کی زائل ہوچکی تھی.حوباب نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نظام تجویز کیا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب ؑ کے اثر
Page 340
سے متاثر ہوکر تھا کیونکہ جیسا کہ ہر نبی کی قوم کو ترقی عطا ہوتی ہے ضرور ہے کہ حضرت شعیب پر ایمان لانے والوں کو بھی ترقی ملی ہو اور چونکہ ان کا زمانہ قریب کا تھا ان کے تمدن کے آثار ابھی تازہ ہوں گے اور انہی سے متاثر ہوکر حوباب نے جو معلوم ہوتا ہے کہ شعیب کی امت میں سے تھے ایک نظام تجویز کیا جو موسیٰ کی قوم میں جاری ہوا.بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ١ۚ۬ وَ مَاۤ اَنَا اگر تم (سچے) مومن ہو تو( یقین جانو کہ) اللہ (تعالیٰ) کا (تمہارے پاس) باقی چھوڑا ہوا( مال ہی) تمہارے لئے عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ۰۰۸۷ بہتر (اور مبارک ہے) اور میں تم پر کوئی محافظ (بنا کر) نہیں (بھیجا گیا).حلّ لُغَات.بَقِیَّۃٌ.اَلْبَقِیَّۃُ اِسْمٌ لِّمَابَقِیَ بقیہ حصہ.وَمَثَلٌ فِی الْجَوْدَۃِ وَالْفَضْلِ یُقَالُ فُلَانٌ بَقِیَّةُ الْقَوْمِ اَیْ مِنْ خَیَارِھِمْ.بقیہ کا لفظ خوبی اور کمال کے بیان کے لئے آتا ہے یعنی جب کسی کو بَقِیَّۃُ الْقَوْمِ کہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے بہترین آدمیوں میں سے ہے.اسی طرح عربی زبان کا محاورہ ہے فِی الزَّوَایَا خَبَایَا وَفِی الرِّجَالِ بَقَایَا.کونوں میں چھپے ہوئے خزانے مل جاتے ہیں اور انسانوں میں اچھے سے اچھے آدمی مل جاتے ہیں.اُولُوْابَقِیَّۃٍ اَیْ اُولُواالرَّأْیِ وَالْعَقْلِ.اور قرآن کریم میں جو اُولُوْا بَقِیَّۃٍ کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہیں عمدہ رائے اور عقل والے لوگ.(اقرب) تفسیر.بَقِيَّتُ اللّٰهِ سے مراد بَقِيَّتُ اللّٰهِ یعنی جو مال نیک ذرائع سے حاصل ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ماتحت ملا ہو.وہ اچھا ہے.اسی پر کفایت کرنی چاہیےاور یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ وہ ترقی کی قابلیتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اگر ان کو استعمال کرو تو تم زیادہ ترقی کرسکتے ہو بہ نسبت ٹھگی کے کاموں کی طرف توجہ کرنے کے.مَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ میں کیا بتایا گیا ہے وَ مَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ میں بتایا ہے کہ یہ خیال نہ کرنا کہ میری وجہ سے عذاب ٹل جائے گا.اگر میری نصیحت کو نہ مانو گے تو ضرور عذاب میں مبتلا ہوجاؤ گے.اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ باوجود انبیاء سے دشمنی کے ان کے پہلے چال چلن اور نمونہ کی وجہ سے لوگ اپنے دلوں میں انہیں ایک خیرو برکت کا موجب وجود ہی خیال کرتے ہیں.مخالفت کی تہہ کے نیچے ادب و احترام کا جذبہ ضرور کام کررہا ہوتا ہے.
Page 341
قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ جس چیز کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے (آئے) ہیں اٰبَآؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا١ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ اسے ہم چھوڑ دیں یا اس بات کو( ترک کر دیں) کہ اپنے مالوں کے متعلق ہم جو چاہیں کریں الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ۰۰۸۸ توتو یقیناً بڑا (ہی) عقل مند( اور) سمجھدار (آدمی) ہے.حلّ لُغَات.الْحَلِیْمُ.الْحَلِیْمُ حَلُمَ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں.صَفَحَ درگزر کیا.سَتَرَ پردہ پوشی کی (اقرب) نیز حِلْمٌ کے معنی ہیں اَلْأَنَاۃُ آرام سے کام کرنا.جوش میں نہ آنا.اَلْعَقْلُ عقلمندی.(اقرب) پس حلیم کے معنی آرام سے بغیر جوش کے کام کرنے والے اور عقلمند کے بھی ہوئے.(اقرب) اَلرَّشِیْدُ.اَلرَّشِیْدُ.ذُوالرُّشْدِ.رشد والا اَلَّذِیْ حَسُنَ تَقْدِیْرُہٗ فِی مَاقَدَّرَ.جو اندازہ درست لگاتا ہو.فِی صِفَاتِ اللہِ آلھَادِیُ اِلٰی سَوَآءِ الصِّرَاطِ.اللہ تعالیٰ کے لئے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دینے والے کے ہوتے ہیں.(اقرب) تفسیر.قومِ شعیب کا تمسخر میرے نزدیک یہ بھی انہوں نے تمسخر کے طور پر کہا ہے اور مطلب یہ ہے کہ سوائے نماز کے تم میں ہم اور تو کوئی خوبی نہیں دیکھتے.نہ محنت کرنا جانتے ہو نہ تجارت کرنا نہ زراعت کرنا.پس کیا تم چاہتے ہو کہ ہم بھی تمہاری طرح دنیا کی عزتوں کو کھودیں اور نکمے ہوکر بیٹھ جائیں.’’کیا نماز تم کو حکم دیتی ہے‘‘ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نماز پڑھ پڑھ کر تمہاری عقل ماری گئی ہے.اور تم خیال کرنے لگے ہو کہ سب سے بڑا کام یہی ہے لیکن تم کو اس سے کیا کام کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے مالوں کو کس طرح خرچ کرتے ہیں.یہ عجیب لطیفہ ہے کہ حضرت شعیب ؑ تو انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دوسروں کے مالوں کو جھوٹ اور فریب سے نہ لیا کرو اور وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ہم جس طرح چاہیں اپنے مالوں کو استعمال کریں.گویا حرام کھاتے کھاتے
Page 342
یہ عجیب لطیفہ ہے کہ حضرت شعیب ؑ تو انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دوسروں کے مالوں کو جھوٹ اور فریب سے نہ لیا کرو اور وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ہم جس طرح چاہیں اپنے مالوں کو استعمال کریں.گویا حرام کھاتے کھاتے ان کی عقل پر اس قدر پردہ پڑ گیا تھا کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ اپنے مالوں میں نہیں بلکہ دوسرے کے مالوں میں تصرف کررہے ہیں.قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ اس نے کہا اے میری قوم (بھلا )بتاؤ (تو سہی) اگر( ثابت ہوا) کہ میں( اپنے دعویٰ کی بنا )اپنے رب کی طرف رَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا١ؕ وَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى سے (عطا شدہ) کسی روشن دلیل پر (رکھتا) ہوں اور اس نے اپنے حضور سے مجھے اچھا (اور پسندیدہ) رزق دیا ہے مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ١ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ١ؕ (تو کل خدا کے حضور تم کیا جواب دو گے )اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکوں (اس سے تم تو رک جاؤاور وَ مَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ١ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ۰۰۸۹ خود میں) تمہارے خلاف اسی (بات) کا قصد کروں.میں تو سوائے اس( حد تک) اصلاح کےجس کی مجھے طاقت ہو کچھ نہیں چاہتا اور میرا توفیق پانا اللہ (تعالیٰ) ہی (کے فضل اور رحم) سے (وابستہ) ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں بار بار جھکتا ہوں.حلّ لُغَات.خَالَفَہٗ خَالَفَہٗ اِلَی کَذَا کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ جو کام وہ کرتا ہے اس کے خلاف کام کیا.تَقُوْلُ خَالَفَنِیْ اِلَی کَذَا.اِذَا قَصَدَہٗ وَاَنْتَ مُوَلٍّ عَنْہُ یعنی اس نے فلاں کام جو تم نہیں کرتے کرکے تمہارے خلاف راہ اختیار کی.(اقرب) تفسیر.حضرت شعیب کا جواب جواب شرط محذوف ہے اور مراد یہ ہے کہ میری نماز مجھے نہیں کہتی بلکہ میرا خدا مجھے کہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادلائل کلام مجھ پر نازل ہو اور وہ اپنے فضل سے حلال رزق مجھے دے تو بتاؤ کہ کیا پھر بھی میرا حق نہیں کہ میں تم کو نصیحت کروں اور اس بات سے روکوں جسے میں بدلائل نقصان دہ ثابت کرچکا ہوں.
Page 343
ان کے اس سوال کا جواب کہ کیا تم ہمیں اس امر سے روکتے ہو کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کریں.یہ دیا کہ خود میرا اپنا رویہ دیکھ لو کہ کیا میں اس تعلیم پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں اگر میں خود بھی عامل ہوں تو میری نیک نیتی تو ثابت ہے.اور اگر یہ خیال ہو کہ میں حکومت کرنی چاہتا ہوں تو یہ خیال تمہارا درست نہیں.حکومت کے بغیر بھی انسان کو نصیحت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے.اور اس حق سے جہاں تک ہوسکے گا میں فائدہ اٹھاؤں گا.باقی رہے نتائج سو ان سے مجھے کوئی تعلق نہیں.میرا کام سمجھانا ہے اور ان کے نتائج پیدا کرنا خدائےتعالیٰ کے اختیار میں ہے.نبوت کے مقام کی کیسی لطیف تشریح ہے.ہر مامور کے سامنے یہی مشکلات پہلے آتی ہیں.بلکہ ہر مبلغ کے سامنے بھی.پہلے پہلے لوگ اس کی باتوں سے بہت گھبراتے ہیں.اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے وعظ سے ان پر جبر کرتا ہے.پھر مساوات دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا جو کچھ کہنا ہے کہتے جاؤ.مگر نبی نہ اس وقت جب لوگ ناراض ہوتے ہیں اور نہ اس وقت جب لوگ پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے کام سے رکتے ہیں.بلکہ دونوں حالتوں میں یکساں جدوجہد سے کام لیتے چلے جاتے ہیں.اور صرف خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھتے ہیں.اور اس کے سوا ہر اک چیز کو بھلا دیتے ہیں.وَ يٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْۤ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَاۤ اور اے میری قوم (دیکھنا کہیں تمہاری ) مجھ سے دشمنی تمہیں یہ بات حاصل نہ کر وا دے کہ تم پر ویسی اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ١ؕ وَ مَا (ہی)مصیبت آئے جیسی کہ نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر مصیبت آئی تھی اور قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ۰۰۹۰ لوط کی قوم( تو) تم سے کچھ( ایسی) دور کی( بھی) نہیں ہے.حلّ لُغَات.جَرَمَ جَرَمَ لِاَھْلِہٖ.کَسَبَ کمایا.وَمِنْہُ فِی الْقُرْآنِ لَایَجْرِمَنَّکُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰی اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا.اَیْ لَایَکْسِبَنَّکمْ.یعنی کسی قوم کی دشمنی کے نتیجہ میں تمہارے دل میں بے انصافی نہ پیدا ہو
Page 344
جائے.وَفُسِّرَ اَیْضًا بِلَا یَحْمِلَنَّکُمْ اور اس کے معنی آمادہ کرنے کے بھی کئے گئے ہیں.(اقرب) اَصْلُ الْجَرْمِ قَطْعُ الثَّمَرَۃِ عَنِ الشَّجَرِ.جَرْم کے اصل معنی درخت سے پھل توڑنے کے ہیں.وَاسْتُعِیْرَ ذٰلِکَ لِکُلّ اِکْتِسَابٍ مَکْرُوْہٍ اور پھر بطور توسیع و استعارہ اسے ہرناپسندیدہ کمائی کے لئے استعمال کیا جانے لگا ہے.وَمَعْنٰی جَرَمَ کَسَبَ أَوْجَنَی اور جرم کے معنی کمانے یا پھل توڑنے کے یا کسی جرم کا ارتکاب کرنے کے ہیں.(مفردات) تفسیر.حضرت شعیب کے زمانہ کی تعیین اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب نوح ہود صالح ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد گزرے ہیں.لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے کیونکہ ان کی قوم کا کوئی ذکر نہیں.حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اسی علاقہ میں اپنی قوم کو لاکر رہے ہیں کہ جس میں ان کی قوم بستی تھی.وَ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ١ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ اور تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو.(اور) پھر اس کی طرف کامل رجوع اختیار کرو میرا رب یقیناً بار بار رحم کرنے وَّدُوْدٌ۰۰۹۱ والا( اور) بہت ہی محبت کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.وَدُوْدٌ.اَلْوَدُوْدُ الْکَثِیْرُ الْحُبِّ.بہت محبت کرنے والا.فَعُوْلٌ بِمَعْنَی الْفَاعِلِ یُقَالُ ھُوَ وَدُوْدٌ وَھِیَ وَدُوْدٌ.یہ لفظ فعول کے وزن پر ہے اور مبالغۂ فاعل کے معنی دیتا ہے.اس وجہ سے مذکر و مؤنث میں کوئی فرق نہیں.اَلْوَدُوْدُ فِی الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی مَعَنَاہُ الْمُحِبُّ اَوِالْمَحْبُوْبُ مِنْ اَوْلِیَاءِ ٖہ فَیَکُوْنِ بِمَعْنٰی مَفْعُولٍ اور ودود اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ہے.اور اس کے معنی محبت کرنے والے کے ہیں یا اولیاء اللہ کا محبوب ہونا اس سے مراد ہے.اس صورت میں اس لفظ کے معنی فاعل کے نہیں بلکہ مفعول کے ہوں گے.(اقرب) تفسیر.توبہ کی حقیقت ہمیشہ دشمنانِ اسلام اسلام پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام توبہ کا دروازہ کھول کر گناہ کا راستہ کھولتا ہے(ستیارتھ پرکاش باب ۱۴ صفحہ ۶۶۹).توبہ کے معنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ سے میری توبہ میری توبہ کہہ دیا اور بس اسی قدر گنہ کی معافی کے لئے کافی ہے.حالانکہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں.اسلامی توبہ بالکل اور چیز ہے.اسلام نے بدی سے نیکی کی طرف آنے اور نیکی سے اعلیٰ مقامات کی طرف جانے کو صرف ایک مقام نہیں قرار دیا بلکہ اسلام بتاتا ہے کہ یہ دونوں کام کئی مدارج طے کرنے کے بعد پورے ہوتے ہیں.ایک گنہ گار جب
Page 345
خدا تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے تو پہلے اس میں محاسبہ کا مادہ پیدا ہوتا ہے یعنی وہ اپنے نفس کا مطالعہ کرکے اس کی غلطیوں کو پکڑتا ہے تب اس میں ندامت پیدا ہوتی ہے اس کے بعد وہ استعاذہ کرتا ہے.یعنی ان گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے.لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے بھی مدد لیتا ہے اس کے بعد وہ استغفار کرتا ہے یعنی پچھلے گناہوں کے بداثرات سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا ہے.اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے یعنی پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگ جاتا ہے.اور اس سے اپنا پیوند جوڑ لیتا ہے.غرض توبہ کے معنی منہ سے معافی مانگنے کے ہرگز نہیں ہوتے.بلکہ یہ بدی سے نیکی کی طرف آنے یا نیکی کے کسی مقام سے اس کے دوسرے مقام کی طرف جانے کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے اور توبہ پر اس تشریح کے بعد اعتراض کوئی علم النفس سے جاہل انسان ہی کرسکتا ہے.یاد رہے کہ جو مدارج میں نے اوپر بیان کئے ہیں یہ سب اور ان سے زیادہ قرآن کریم میں مذکور ہیں یہاں اختصار کی غرض سے تفصیلاً ان کا ذکر نہیں کیا گیا.قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَ اِنَّا انہوں نے کہا اے شعیب جو کچھ تو کہتا ہے اس میں سے بہت سا (حصہ) ہماری سمجھ میں نہیں آتا.اور ہم تجھے اپنے لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا١ۚ وَ لَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ١ٞ وَ مَاۤ درمیان یقیناً یقیناً ایک کمزور( آدمی) سمجھتے ہیں اور اگر تیرا گروہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے.اور تو(بذات خود) اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ۰۰۹۲ ہماری نظر میں کوئی قابل عزت( وجود) نہیں ہے.حلّ لُغَات.رَھْطٌ اَلرَّھْطُ قَوْمُ الرَّجُلِ وَقَبِیْلَتُہٗ آدمی کی قوم اور اس کا قبیلہ وَعَدَدٌ یُجْمَعُ مِنَ الثَّلَاثَۃِ اِلَی الْعَشَرَۃِ وَلَیْسَ فِیْہِمْ اِمْرَءَ ۃٌ وَلَا وَاحِدَ لَہٗ مِنْ لَفْظِہٖ.وَجَمْعُہٗ اَرْھَطٌ وَارْھَاطٌ.وَجَمْعُہَا اَرَاھِطُ وَاَرَاھِیْطُ وَ ِفی الْقُرْاٰنِ.وَکَانَ فِی الْمَدِیْنَۃِ تِسْعَۃُ رَھْطٍ.اَیْ تِسْعَۃُ اَنْفُسٍ.یعنی رہط کے معنی اتنی تعداد کے افراد کے ہوتے ہیں جس میں تین سے لے کر دس تک وجود شامل ہوں.بشرطیکہ ان میں عورت کوئی نہ ہو.سب مرد ہوں.اور اس لفظ کا واحد کوئی نہیں آتا.اور اس کی جمع اَرْھَطٌ اور اَرْھَاطٌ ہے اور جمع الجمع اَرَاھِطُ اور
Page 346
اَرَاھِیْطُ ہے.قرآن کریم میں ان معنوں میں یہ لفظ آیا ہے.چنانچہ فرماتا ہے تِسْعَۃُ رَھْطٍ یعنی نو افراد (اقرب) اَلْعَزِیْزُ.اَلْعَزِیْزُ الشَّرِیْفُ عزت والا.اَلْقَوِیُّ.مضبوط.اَلْقَلِیْلُ النَّادِرُ لَا یَکَادُ یُوْجَدُ.نادر الوجود جس کی مثل ملنی مشکل ہو.اَلْمُکَرَّمُ معزز.وَجَمْعُہٗ عِزَازٌ واعِزَّةٌ واَعِزَّاءُ اور اس کی جمع عِزَازٌ.اَعِزَّۃٌ اور اَعِزَّاءُ ہے.وَالْعَزِیْزُ اَیْضًا مِنَ اَسْمَاءِ اللہِ تَعَالیٰ وَھُوَ الْمَنِیْعُ الَّذِیْ لَا یُنَال وَلَایُغَالَبُ وَلَا یُعْجِزُہُ الشَّیْءُ وَلَا مِثْلَ لَہٗ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ ہستی کہ جس تک پہنچنا تمام طاقت سے بالا ہے اور جس پر کوئی غالب نہیں آسکتا.نہ اسے اس کے کام سے کوئی چیز روک سکتی ہے اور اس کی کوئی مثل نہیں اَلْمَلِکُ لِغَلَبَتِہٖ عَلَی اَھْلِ مَمْلِکَتِہٖ.بادشاہ کو بھی عزیز کہتے ہیں کیونکہ اسے اپنی رعایا پر غلبہ حاصل ہوتا ہے.لَقَبٌ مِنْ مَلَکَ مِصْرَ مَعَ الْإِسْکَنْدَرِیَّہِ وہ بادشاہ جو مصر اور سکندریہ دونوں کا بادشاہ ہو اسے بھی عزیز کہتے ہیں.(اقرب) قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ فراعنہ کے زمانہ میں وزیر مالیہ کو بھی عزیز کہتے تھے.ظِھْرِیٌّ.اَلظِّھْرِیُّ الَّذِیْ تَجْعَلُہٗ وَرَآءَ ظَھْرِکَ وَتَنْسَاہُ وَتَغْفُلُہٗ.جسے تو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دے اور اسے بھول جائے اور اس سے غافل ہو جائے.(اقرب) تفسیر.انبیاء کی خدا کے لئے غیرت نبی کی غیرت کو دیکھو اور کوئی ہوتا تو خوش ہوتا کہ میری قوم ایسی مضبوط ہے کہ اس کی وجہ سے میری حفاظت ہورہی ہے اور شاید اس امر پر اور زور دیتا کہ مجھے چھیڑ کر دیکھو تو سہی کہ میری قوم تم سے کیسا سلوک کرتی ہے.لیکن حضرت شعیب علیہ السلام الٹے ناراض ہوتے ہیں.اور کہتے ہیں کہ کیا میری قوم خدا تعالیٰ سے بڑی ہے کہ تمہیں اس کا لحاظ ہے مگر خدا تعالیٰ کا نہیں؟ میری قوم کے ڈر سے مجھے کچھ نہیں کہنا چاہتے.لیکن خدا کا خوف نہیں کرتے اور دھوکے اور لوٹ سے باز نہیں آتے.اس جوش میں حضرت شعیب علیہ السلام اس امر کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اس طرح وہ اپنی قوم کی تحقیر کرکے اسے بھی غصہ دلا رہے ہیں.صرف ایک ہی بات ان کے خیالات پر حاوی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کا مقام ہے.
Page 347
قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْۤ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ١ؕ وَ اتَّخَذْتُمُوْهُ۠ اس نے کہا اے میری قوم کیا میرا گروہ اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہاری نظر میں زیادہ قابل عزت ہے اور اسے وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا١ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَاتَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ۰۰۹۳ تم نے بھلاتے ہوئے بالکل پیٹھ کے پیچھے کیا ہوا ہے.جو کچھ تم کرتے ہو اسے میرا رب یقیناً خوب جانتاہے.تفسیر.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اللہ کا ایک نمونہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کئی مواقع پیش آئے ہیں.اور آپ نے ان مواقع پر اپنی شان کے مطابق محبت الٰہی کے نظارے دکھائے ہیں.مثلاً احد کے موقع پر جب اسلامی لشکر پراگندہ ہو گیا اور صرف چند آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ قتل ہو گئے.اس وقت ابوسفیان نے آواز دے کر پکارا.کہ اے مسلمانو! ہم نے تمہارے رسول کو مار دیا ہے.گو یہ بات غلط تھی مگر موقع کی نزاکت کو دیکھ کر آپ نے جواب دینے سے روک دیا تادشمن اس پراگندگی سے فائدہ اٹھا کر دوبارہ حملہ نہ کردے اس کے بعد ابوسفیان نے کہا کہ اگر ابوبکر ہے تو بولے آپ نے ان کو بھی روک دیا.اس پر اس نے نعرہ لگایا کہ ہم نے اسے بھی مار دیا ہے.پھر اس نے کہا کہ عمر کہاں ہیں.حضرت عمر نے جوش میں آکر کہا کہ عمر تمہارا سر کچلنے کو موجود ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بولتے بولتے روک دیا.اس پر ابوسفیان نے بڑے زور سے نعرہ لگایا کہ اُعْلُ ھُبَلْ اُعْلُ ھُبَلْ کہ ھبل کی شان بلند ہو یعنی ہمارے بت جیت گئے.اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کرسکے اور فرمایا کہ اب کیوں نہیں بولتے.کہو اَللہُ اَعْلیٰ وَ اَجَلُّ.اللہ ہی سب سے بلند و برتر اور سب سے زیادہ شوکت والا ہے.دشمن کے نرغہ میں گھرے ہوئے اور جب سب لشکر پراگندہ ہو چکا تھا خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف لفظ سن کر آپ کس طرح بے تاب ہو گئے.اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ اس فقرہ کے ساتھ ان کو ڈرایا ہے کہ خدا تعالیٰ اس غیرت میں آکر کہ تم نے میری قوم کو اس سے زیادہ سمجھا کہیں تمہارے اعمال کو تباہ کرکے تم پر عذاب نہ نازل کردے اور یہ تجارتیں وغیرہ سب برباد ہو جائیں.اور تم لوگ کنگال ہو جاؤ.
Page 348
وَ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ١ؕ سَوْفَ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ پر (اپنے) کام کئے جاؤ.میں(بھی اپنی جگہ پر) یقیناً کام کر رہا ہوں.عنقریب تمہیں تَعْلَمُوْنَ١ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ١ؕ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے.جو اسے رسوا کر دے گا اور کون جھوٹا ہے اور تم( بھی اپنے وَ ارْتَقِبُوْۤا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ۰۰۹۴ اور میرے انجام کا) انتظار کرو میں (بھی) یقیناً تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں.حلّ لُغَات.مَکَانَۃٌ.اَلْمَکَانَۃٌ اَلْمَوْضِعُ.وَالْمَنْزِلَۃُ.جگہ اور درجہ (اقرب) اِرْتَقَبَ اِرْتَقَبَ فُلَانًا وَالشَّیْءَ اِنْتَظَرَہٗ.فلاں شخص یا فلاں چیز کا انتظار کیا.(اقرب) رَقِیْبٌ اَلرَّقِیْبُ مِنْ صِفَاتِ اللہِ تَعَالٰی.اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور اس جگہ معنی ہیں اَلْحَافِظُ نگراں اَلْمُنْتَظِرُ.منتظر الحَارِسُ پہرہ دار اِبْنُ الْعَمِّ چچا کا بیٹا.رَقِیْبُ الْجَیْشِ.طَلِیْعَتُھُمْ.راستہ کے آگے آگے چلنے والا جو راستہ کی حالت اور اس کے خطرات کی خبر لیتا چلا جاتا ہے.(اقرب) تفسیر.یعنی تم اپنے مقام کے لحاظ سے عمل کرتے جاؤ.میں اپنی روش کے مطابق عمل کرتا چلا جاؤں گا.آخر نتائج بتا دیں گے کہ کون اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق عمل کررہا تھا اور کون اس کے خلاف.نبی ہمیشہ یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ خدا پر فیصلہ چھوڑو اور انتظار کرو.مگر لوگ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں ہی فیصلہ رکھتے ہیں.خدا تعالیٰ پر نہیں چھوڑتے اور آخر اس کی سزا بھگتتے ہیں.اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ میں بتایا ہے کہ چاہیےتو یہ تھا کہ میں گھبراتا کیونکہ میں مصیبت میں ہوں.میرے ساتھیوں کو تم تکلیفیں دیتے ہو لیکن گھبرا تم رہے ہو.حالانکہ چاہیےیہ کہ ہم دونوں خدا کے فیصلے کا انتظار کریں.وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ اور جب ہمارا( عذاب کا) حکم آگیا تو ہم نے شعیب کو اور ان (لوگوں) کو جو اس کے ساتھ( یگانگت اختیار کرتے
Page 349
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ اَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ہوئے اس پر) ایمان لائے تھے اپنی (خاص) رحمت سے (اس عذاب سے )بچا لیا.اور جنہوں نے ظلم (کا شیو ہ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَۙ۰۰۹۵كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا١ؕ اختیار) کیا تھا انہیں اس عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنے (اپنے) گھروں میں زمین سے لپٹے ہوئے ہو گئے.گویا وہ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُؒ۰۰۹۶ ان میں (کبھی) رہے( ہی) نہ تھے سنو! مدین کے لئے بھی( خدا کی جنا ب سے) دوری (ہو گئی) تھی.جیسا کہ ثمود (خدا کی جناب سے) دور ہو گئے تھے.تفسیر.حضرت شعیب ایسے علاقہ میں تھے کہ جس میں زلزلے بہت کثرت سے آتے ہیں.ممکن ہے کہ آیت کے ظاہری الفاظ کے مطابق ان کی قوم پر زلزلہ کا عذاب آیا ہو لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ صیحہ سے مراد عام عذاب ہو.اور گھٹنوں کے بل گرے ہوئے کے الفاظ مجازاً استعمال ہوئے ہوں.کسی اورعذاب سے اس قوم کی شان و شوکت توڑ دی گئی ہو اور یہ لوگ ذلیل ہوکر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہوں.وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍۙ۰۰۹۷اِلٰى اور ہم نے موسیٰ کو یقیناً یقیناً اپنے( ہر قسم کے) نشان اور روشن دلیل دے کر بھیجا تھا.(ہم نے اسے) فرعون اور اس فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡىِٕهٖ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ١ۚ وَ مَاۤ اَمْرُ فِرْعَوْنَ کی قوم کے بڑے لوگوں کی طرف (بھیجا تھا) تو انہوں نے (ہمارے حکم کے خلاف) فرعون کے حکم کی پیروی کی اور بِرَشِيْدٍ۰۰۹۸ فرعون کا حکم ہرگز درست نہ تھا.حلّ لُغَات.سُلْطَانٌ.اَلسُّلْطُانُ الْحُجَّۃُ محکم دلیل.تَـقُوْلُ لَہٗ سُلْطَانٌ مُّبِیْنٌ.اَیْ حُـجَّۃٌ.یعنی
Page 350
جب کسی کے متعلق کہیں کہ لَہُ سُلْطَانٌ مُبِیْنٌ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاس روشن اور محکم دلیل ہے.(اقرب) تفسیر.اس جگہ موسیٰ ؑکے ذکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں نہیں اس جگہ حضرت موسیٰ ؑ کی بعثت کے اس حصہ پر بحث ہے جو سزا ہی سزا کا رنگ رکھتا تھا.یعنی آپ کی بعثت فرعون اور اس کی قوم کی طرف.یہ قوم ایمان نہ لائی اور تباہ کردی گئی اور یہی بحث اس سورۃ میں ہے.بنی اسرائیل کا ذکر اس سورۃ میں نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایمان لائے اور نعمتوں کے وارث ہوئے.فرعون کسی خاص شخص یا خاندان کا عَلم نہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ فرعون شاہان مصر کا لقب ہوا کرتا تھا.یعنی وادی نیل اور سکندریہ کا حکمران فرعون کہلاتا تھا.یہ اصطلاح رومیوں کے آنے سے پہلے پہلے تھی.رومیوں کے آنے پر حکومت غیرملکیوں میں چلی گئی اور فرعون کا لفظ مٹ گیا.کیونکہ ان کے ہاں اپنے الگ القاب تھے.دوسرے یہ کہ فرعون کسی ایک ہی خاندان کے بادشاہوں کا نام نہیں تھا بلکہ کئی خاندان گذرے ہیں جنہوں نے تین چار ہزار سال تک حکومت کی ہے.کسی خاندان کے دس بادشاہ گزرے کسی کے بیس.فرعون کو بنی اسرائیل کی طرف سے خطرہ کی وجہ مختلف خاندانوں کے حکمرانوں کو جنہوں نے وادی النیل اور سکندریہ پر حکومت کی یکے بعد دیگرے فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا.یہ فرعون بھی جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے بنی اسرائیل کی طرح غیرملکی تھا.اور اس لئے وہ بنی اسرائیل کی کثرت اولاد سے ڈرتا تھا اور اسے خوف تھا کہ مبادا وہ ملک کے اصلی باشندوں سے مل کر اس کو ملک سے نکال دیں.یا بغاوت و جنگ کے لئے کھڑے ہوجائیں.جیسا کہ خروج باب۱ آیت ۹،۱۰ میں لکھا ہے ’’اس نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں.آؤ ! ہم ان سے دانشمندانہ معاملہ کریں تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں.‘‘ ’’ہم سے زیادہ ‘‘ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہمارے خاندان یا نسل سے زیادہ ہیں نہ یہ کہ وہ تمام اہل ملک سے زیادہ ہیں.موسیٰ کے متعلق بائبل اور قرآن کریم کے بیان میں اختلاف انہی دنوں میں جبکہ فرعون بنی اسرائیل پر تشدد کررہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی.خروج باب ۲،۳،۴ میں ان کی پیدائش جوانی اور زندگی کے
Page 351
حالات مذکور ہیں.وہ بیان قرآن مجید سے بعض باتوں میں مختلف ہے.موسیٰ کو ان کی والدہ نے کہاں رکھا تھا (۱)بائبل کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ ؑ کی والدہ نے ان کو دریا میں نہیں ڈالا تھا بلکہ دریا کے کنارے ایک جھاؤ کے نیچے ایک ٹوکرے میں چھپا دیا تھا.چنانچہ لکھا ہے ’’تو اس نے (یعنی موسیٰ ؑ کی والدہ نے) سرکنڈوں کا ایک ٹوکرہ بنایا اور اس پر لاسہ اور رال لگایا اور لڑکے کو اس میں رکھا اور اس نے اسے دریا کے کنارے پر جھاؤ میں رکھ دیا.‘‘ (خروج ۳/۲) لیکن قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس بچے کو دریا میں ڈال دیا تھا.جیسا کہ فرمایا اِذْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّكَ مَا يُوْحٰۤى.اَنِ اقْذِفِيْهِ فِي التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيْ وَ عَدُوٌّ لَّهٗ (طٰہٰ :۳۹.۴۰) کیا موسیٰ ؑنے مصری کو دانستہ قتل کیا تھا (۲)بائبل کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبرانی اور مصری کے جھگڑے میں مصری کو عمداً مار ڈالا جیسا کہ لکھا ہے ’’دیکھا کہ ایک مصری ایک عبرانی کو جو اس (موسیٰ ؑ) کے بھائیوں میں سے ایک تھا مار رہا ہے.پھر اس نے ادھر ادھر نظر کی اور دیکھا کہ کوئی نہیں تب اس مصری کو مار ڈالا اور ریت میں چھپا دیا.‘‘ (خروج ۱۱،۱۲؍۲) مگر قرآن مجید فرماتا ہے فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ١ٞۗ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَ هٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ١ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ١ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ (القصص :۱۶) یعنی حضرت موسیٰ ؑ نے مصری کو صرف تنبیہہ کے طور پر ایک مکا مارا ان کا ارادہ قتل کا نہ تھا.مگر وہ اتفاقاً مر گیا.گویا بائبل حضرت موسیٰ ؑ کو قاتل قرار دیتی ہے مگر قرآن مجید ان کی بریت کرتا ہے.کیا دوسرے دن جھگڑنے والے دونوں عبرانی تھے (۳)بائبل کہتی ہے کہ پہلے دن کے جھگڑے کے بعد دوسرے دن حضرت موسیٰ ؑ نے دو عبرانیوں کو لڑتے دیکھا چنانچہ لکھا ہے.’’جب وہ دوسرے دن باہر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دو عبرانی آپس میں جھگڑ رہے ہیں.تب اس نے اس کو جو ناحق پر تھا کہا کہ تو اپنے یار کو کیوں مارتا ہے.وہ بولا کس نے تجھے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا.آیا تو چاہتا ہے کہ جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالے.‘‘ (خروج ۱۳،۱۴/۲)مگر قرآن مجید فرماتا ہے کہ دوسرے دن بھی ایک مصری اور ایک عبرانی ہی لڑرہے تھے.جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَآىِٕفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُهٗ١ؕ قَالَ لَهٗ مُوْسٰۤى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ.فَلَمَّاۤ اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِيْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا١ۙ قَالَ يٰمُوْسٰۤى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِيْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِالْاَمْسِ١ۖۗ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَ مَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ
Page 352
الْمُصْلِحِيْنَ.(القصص :۱۹.۲۰) حضرت شعیب کی لڑکیوں کے گلّے کو پانی پلانے کا واقعہ (۴)بائبل کہتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ ؑ فرعون سے بھاگ کر مدین پہنچے تو انہیں مندرجہ ذیل واقعہ پیش آیا ’’اور مدیان کے کاہن کی سات بیٹیاں تھیں.وہ آئیں اور پانی نکالنے لگیں اور گھڑوں کو بھرا.تاکہ اپنے باپ کے گلے کو پانی پلائیں.تب گڈریوں نے آ کے انہیں ہانکا لیکن موسیٰ نے کھڑے ہوکر ان لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے گلے کو پانی پلایا.‘‘ (خروج باب۲ آیت ۱۶،۱۷) مگر قرآن مجید کا بیان اس سے مختلف ہے.قرآن مجید اس واقعہ کو یوں بیان فرماتا ہےوَ لَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ١ٞ وَ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدٰنِ١ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا١ؕ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ١ٚ وَ اَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ.فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰۤى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّيْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ.(القصص :۲۴.۲۵) کہ جب حضرت موسیٰ ؑ مدین کے پانی پر وارد ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ (اپنے مویشیوں کو) پانی پلا رہا ہے.اور دو لڑکیاں اپنے گلّے کو پرے روکے کھڑی ہیں.حضرت موسیٰ ؑ نے ان سے پوچھا تم الگ کیوں کھڑی ہو.انہوں نے جواب دیا کہ جب چرواہے چلے جائیں گے تب ہم پانی پلا سکیں گی.کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا اور عمر رسیدہ ہے.اس جگہ پر قرآن مجید کی تعلیم کیا ہی اعلیٰ اخلاق والی اور پاکیزہ ہے.وہ بتاتا ہے کہ ان لڑکیوں کا پرے رہنا ان کی شرم کی وجہ سے تھا.اس بیان میں قرآن مجید تورات سے کئی باتوں میں اختلاف کرتا ہے.(الف) بائبل کہتی ہے مدین کے کاہن کی سات بیٹیاں پانی پر آئیں اور قرآن مجید فرماتا ہے دو لڑکیاں آئی تھیں.(ب) بائبل کہتی ہے لڑکیوں نے گھڑوں کو پانی سے بھرا اور چرواہوں نے آکر ان کو روکا اور قرآن مجید فرماتا ہے وہ لڑکیاں آگے نہیں بڑھیں بلکہ شرم کے مارے گلے کو روکے کھڑی رہیں.(ج) بائبل کہتی ہے حضرت موسیٰ ؑ نے گڈریوں کا مقابلہ کیا اور لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور قرآن مجید فرماتا ہے مقابلہ وغیرہ کوئی نہیں ہوا ہاں حضرت موسیٰ ؑ نے اسی دوران میں ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا.کیا حضرت موسیٰ ؑنے فرعون کو دھوکہ دے کر بنی اسرائیل کو نکالا تھا؟ (۵)بائبل کے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال لا.مگر شاہ مصر کو نہ بتلانا کہ ہم بھاگ رہے ہیں.بلکہ لکھا ہے کہ’’ تو اور اسرائیلیوں کے بزرگ مصر کے بادشاہ کے پاس آئیو اور اسے کہیئو کہ
Page 353
خداوند عبرانیوں کے خدا نے ہم سے ملاقات کی اور اب ہم تیری منت کرتے ہیں ہم کو تین دن کی راہ بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لئے قربانی کریں.‘‘ (خروج ۱۸/۳) گویا ایک طرح سے دھوکہ کی تعلیم دی ہے.مگر قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ تم اس کے پاس جاکر یہ کہنا اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ١ۙ۬ وَ لَا تُعَذِّبْهُمْ (طٰہٰ :۴۸) کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں.اور اس لئے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے.کیا بنی اسرائیل کو لوگوں کے زیورات ساتھ لےجانے کا حکم دیا گیا تھا (۶)بائبل کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ؑ سے کہا ’’ہر ایک عورت اپنی پڑوسن سے اور اس سے جو اس کے گھر میں رہتی ہے روپے اور سونے کے برتن اور لباس عاریتاً لے گی اور تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو غارت کروگے.‘‘ (خروج ۲۲/۳) مگر قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ زیور ساتھ لے آنا.بلکہ وہ خود ہی لے آئے تھے اور یہ ان کی خیانت اور غداری تھی.جیسا کہ فرماتا ہے وَ لٰكِنَّا حُمِّلْنَاۤ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ (طٰہٰ :۸۸) جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس دھوکہ کے خود ذمہ دار تھے.اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا.حضرت موسیٰ کا ید بیضا کیا مبروص تھا ؟ (۷)بائبل میں حضرت موسیٰ ؑ کے معجزۂ ید بیضاء کے متعلق لکھا ہے ’’چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ اپنی چھاتی پر چھپاکے رکھا.اور جب اس نے اسے نکالا تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ برف کی مانند سفید مبروص تھا.‘‘ (خروج ۶/۴) یعنی ہاتھ سفید تھا.مگر برص کے عیب کی وجہ سے وہ ایسا تھا اور قرآن مجید فرماتا ہے وَ اضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى (طٰہٰ :۲۳) کہ وہ ہاتھ بے شک روشن اور چمکیلا تھا مگر کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہرگز نہ تھا بلکہ ایک نشان کے طور پر تھا.کیا حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے مادری یا حقیقی بھائی نہ تھے (۸)بائبل حضرت ہارون کے متعلق کہتی ہے کہ حضرت ہارونؑ حضرت موسیٰ ؑ کے خاندان بنی لاوی کا ایک فرد ہونے کی رو سے ان کے بھائی تھے.نہ حقیقی یا مادری بھائی.چنانچہ لکھا ہے.’’ اس (خدا) نے کہا کیا نہیں ہے لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی.میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے.‘‘ (خروج ۱۴/۴) مگر قرآن مجید حضرت ہارونؑ کو موسیٰ ؑ کا سگا بھائی یا ماں کی طرف سے بھائی بتاتا ہے.جیسا کہ فرماتا ہے.قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَ لَا بِرَاْسِيْ.(طٰہٰ:۹۵) کہ حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ ؑ سے عرض کیا اے میری ماں کے بیٹے !میری ڈاڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑ.
Page 354
(۹)بائبل بچھڑے کو معبود بنانے میں حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کا شریک بلکہ اس شرک کا بانی قرار دیتی ہے.چنانچہ لکھا ہے.’’اور خداوند نے ان کے بچھڑے بنانے کے سبب جسے ہارون نے بنایا تھا لوگوں پر مری بھیجی.‘‘ (خروج ۳۵/۳۲) مگر قرآن مجید حضرت ہارونؑ کو اس قسم کے عیب سے بکلی بری قرار دیتا ہے بلکہ فرماتا ہے وَ لَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ١ۚ وَ اِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ وَ اَطِيْعُوْۤا اَمْرِيْ (طٰہٰ:۹۱) یعنی حضرت ہارونؑ نے ان لوگوں کو بچھڑے کی عبادت سے منع کیا تھا.ان اختلافات کے متعلق ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.خود مسیحی کتب ہی بائبل کے بیانات کو مخدوش قرار دیتی ہیں.چنانچہ انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا میں موسیٰ ؑ کے لفظ کے ماتحت لکھا ہے کہ حمورابی تعلیم کا بہت سا حصہ بطور خلاصہ موسیٰ کی کتاب میں آ گیا ہے.نیز ہارون کے شرک کے واقعہ کو بھی اس نے غلط قرار دیا ہے اور اس سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ بائبل میں کئی واقعات بعد میں بڑھا دیئے گئے ہیں.ایک نئی تحقیق بہرحال عقل اور جدید تحقیق دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کا بیان گو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد شائع ہوا درست ہے اور بائبل جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ موسیٰ کے وقت میں لکھی گئی اس کا بیان مشکوک ہے.حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ کیوں رکھا گیا.اس کی وجہ بائبل نے یہ بتائی ہے کہ انہیں پانی سے بچا یا گیا تھا.خروج ب۲ آیت ۱۰ لیکن تعجب یہ ہے کہ باوجود اس کے تورات ان کے پانی سے نکالنے کی منکر ہے.لیکن قرآن کریم اس واقعہ کی تائید کرتا ہے.ہارون کے معنی عبرانی زبان میں کوئی نہیں.موجودہ محققین کہتے ہیں کہ شمالی عرب کی زبانوں میں سے یہ نام ہے.(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Aaron) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک عبرانی لوگ اپنی اصلی زبان یعنی عربی سے تعلق رکھتے تھے.
Page 355
يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ١ؕ وَ بِئْسَ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے( آگے) چلے گا اور ان کو( دوزخ کی) آگ میں (جا) اتارے گا اور وہ (ان الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ۰۰۹۹ کے) اترنے کا گھاٹ بہت (ہی) برا ہے.حلّ لُغَات.قَدَمَ.قَدَمَ الْقَوْمَ.یَقْدُمُ قَدْمًا وَقُدُوْمًا.سَبَقَہُمْ.ان سے آگے نکل گیا.فُلَانٌ عَلٰی قِرْنِہٖ شَجُعَ وَاجْتَرَءَ عَلَیْہِ اپنے دشمن پر دلیری سے حملہ کیا.قَدِمَ عَلی الْعَیْبِ یَقْدَمُ رَضِیَ بِہٖ عیب پر راضی ہو گیا.مِنْ سَفَرِہٖ عَادَ.سفر سے واپس آیا.وَالْبَلَدَ اَ تَاہُ شہر میں آیا.(اقرب) اَوْرَدَ اَوْرَدَہ اِیْرَادًا اَحْضَرَہُ الْمَوْرِدُ.ثُمَّ اسْتُعْمِلَ لِمُطْلَقِ الْاِحْضَارِ.اَوْرَدَ کے اصل معنی ہیں گھاٹ پر لایا.لیکن بعد میں مطلق حاضر کرنے کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہونے لگ گیاہے.اس کا ثلاثی وَرَدَ یَردُ وَرُوْدًا ہے.کہتے ہیں.وَرَدَ الْبَعِیْرُ وَغَیْرُہُ الْمَاءَ وَغَیْرُہٗ بَلَغَہٗ وَدَانَاہُ مِنْ غَیْرِ دُخُوْلٍ.وَقَدْ یَحْصُلُ دُخُوْلٌ فِیْہِ.وَقَدْ لَا یَحْصُلُ.یعنی یہ لفظ اونٹوں وغیرہ کے پانی وغیرہ پر جانے کے معنی دیتا ہے.خواہ وہ اس کے اندر گئے ہوں یا نہ.وَرَدَ زَیْدٌالْمَآءَ خِلَافَ صَدْرَعَنْہُ وَرَدَ کے معنی پانی کی طرف جانے کے بھی ہوتے ہیں.(اقرب) اَلْوِرْدُ.اَلْعَطَشُ پیاس.اَلْاِبِلُ الْوَارِدَۃُ.اونٹ جو پانی پر آئیں.اَلْجَیْشُ.لشکر.اَلْمَاءُ الَّذِیْ یُوْرَدُ گھاٹ.اَلْقَوْمُ یُرِدُوْنَ الْمَآءَ پانی پر وارد ہونے والی جماعت.اَلنَّصِیْبُ مِنَ الْمَآءِ پانی کا حصہ (اقرب) اَلْمَوْرِدُ.گھاٹ.پانی پینے کے لئے اترنے کی جگہ.تفسیر.یعنی عقلمند انسان تو اس چیز کی پیروی کرتا ہے جو اسے صحیح راستہ دکھائے اور اس کے لئے مفید ہو.لیکن فرعون کی ہدایت اس کے برخلاف ہلاکت کی طرف لے جاتی تھی.مگر پھر بھی یہ لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے.اَوْرَدَهُمُ النَّارَ میں بتلایا کہ قوم نے فرعون کا ساتھ دے کر کیا نتیجہ حاصل کیا.یہی نہ کہ اس نے ان کو دوزخ میں لاڈالا.اور یہ گھاٹ نہایت ہی خطرناک گھاٹ ہے.پانی کی بجائے آگ اورد کا لفظ اصل میں پانی پر وارد کرنے کے معنی میں آتا ہے.مگر اس جگہ پر یہی لفظ
Page 356
آگ کے لئے استعمال کرکے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ پانی جو روحانی اور جسمانی حیات کا باعث ہے.چنانچہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ کُلَّ شَیْ ئ ٍحَيٍّ (الانبیاء:۳۱)اس کی بجائے انہیں آگ دی جائے گی جو حیات کو تباہ کرنے والی ہے.اور اس طرح ان کی اپنی کوششیں جو بجائے روحانی حیات کے حصول کے اس کے تباہ کرنے میں خرچ ہوتی تھیں ان کے لئے متمثل ہوجائیں گی.پھر اس کے یہ بھی معنی ہوسکتے ہیں کہ وہ داخل تو آگ میں ہوں گے مگر یہ داخلہ اسی طرح ہوگا جس طرح یہاں پیاسا پانی پر جاتا ہے.یعنی اس ذریعہ سے بھی آخر ان کی روحانی پیاس بجھ جائے گی یعنی آگ ان کے پاک کرنے کا موجب ہو جائے گی اور آخر وہ اس راستہ سے گزر کر اپنی روحانی پیاس کو بجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے.پرانے زمانہ میں داغ دینے کی رسم ہوا کرتی تھی.یعنی جانور کے منہ پر یا پہلو میں نشان لگایا کرتے تھے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند فرمایا(مسلم کتاب السلام باب لکل داء دواء، استحباب التداوی ).لیکن چونکہ علاج کے طور پر بھی داغ دیا جاتا تھا فرمایا کہ اٰخِرُ الدَّوَاءِ الْکَیُّ کہ دوا کے طور پر بھی استعمال کرنا پڑے تو آخری علاج کے طور پر داغ کو استعمال کرو.ایسا ہی یہاں فرمایا کہ پانی کی بجائے ان کی پیاس کا علاج آگ سے کیا جائے گا.اور وہ ان کا آخری اور انتہائی علاج ہوگا.وَ اُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ١ؕ بِئْسَ الرِّفْدُ اور اس دنیا میں (بھی) لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی ہےاور قیامت کے دن (بھی لگا دی جائے گی) یہ عطا جو الْمَرْفُوْدُ۰۰۱۰۰ ( انہیں) دی جانے والی ہے بہت (ہی )بری ہے.حلّ لُغَات.رَفَدَ.رَفَدَہٗ یَرْفِدُ رَفْدًا.اَعْطَاہُ اسے دیا.اَعَانَہٗ.اس کی مدد کی.اور یہی معنی اس لفظ کے اس محاورہ میں ہیں کہ ’’ھُوَ نِعْمَ الرَّافِدُ اِذَا حَلَّ بِہِ الوَافِدُ.‘‘ یعنی فلاں شخص کے پاس جب کوئی (طالب امداد) آتا ہے تو وہ اس کی خوب ہی امداد کرتا ہے.اَلرِّفْدُ الْعَطَاءُ وَالصِّلَۃُ رفد کے معنی بخشش اور انعام کے ہوتے ہیں.وَاَصْلُ الرِّفْدُ مَایُضَافُ اِلَی غَیْرِہٖ لِیَعْمِدَہٗ یعنی اصل میں رفد اس چیز کو کہتے ہیں جسے کسی دوسری چیز کو سہارا دینے کے لئے کھڑا کیا جائے.یعنی ٹیک وَفیِ الْقُرْاٰنِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ.اَیْ العَوْنُ الْمُعَانُ
Page 357
وَالعَطَاءُ الْمُعْطٰی.اور قرآن کریم میں جو بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ آیا ہے.اس کے معنی ہیں مدد جو دی گئی.یا بخشش جو کی گئی.(اقرب) تفسیر.لعنت کا مفہوم یعنی برے آدمی کے پیچھے لگ کر انسان اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اگلے جہان میں بھی.لعنت سے مراد اس جگہ گالی نہیں ہے بلکہ یہاں اس کے اصل معنی یعنی دوری مراد ہے.اور مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ خدا سے دور رہے اور اگلے جہان میں بھی دور ہی رہیں گے.رفد سے مراد یہ بھی ممکن ہے کہ اِلرِّفْدُ سے مراد اس جگہ فرعون ہو.یعنی انہوں نے جو خدا کے مقابلہ میں فرعون کا سہارا لیا تھا وہ کیسا برا ثابت ہوا.جس کی وجہ سے یہ اب تک عذاب دیکھ رہے ہیں.کیونکہ ان کا سہارا یعنی فرعون خود بھی جہنم میں گرا اور ان کو بھی اس نے جہنم میں لا ڈالا.ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآىِٕمٌ وَّ یہ( تباہ شدہ) بستیوں کی خبروں میں سے (ایک حصہ )ہے ہم اسے تیرے پاس بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض حَصِيْدٌ۰۰۱۰۱ (بستیاں ابھی تک موجود) کھڑی ہیں اور بعض کٹی پڑی ہیں.حلّ لُغَات.حَصَدَ.حَصَدَ یَحْصُدُ وَیَحْصِدُ حَصْدًا وحِصَادًا.قَطَعَہٗ بِالْمِنْجَلِ درانتی سے کاٹا.الْقَوْمَ بِالسَّیْفِ قَتَلَہُمْ.تلوار سے قتل کیا.اَلرَّجُلُ مَاتَ.جب لازم استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں مر گیا.(اقرب) تفسیر.قری سے مراد اس جگہ پر اَلْقُرٰی سے دو چیزیں مراد ہوسکتی ہیں.قَائِمٌ وَ حَصِیْدٌ کے معنی (۱)أَھْلُ الْقُرٰی یعنی بستیوں میں رہنے والے جیسا کہ دوسری جگہ آتا ہے.وَاسْئَلِ الْقَرْیَۃَ الَّتِیْ کُنَّا فِیْھَا (یوسف :۸۳) اس بستی والوں سے پوچھ لے.اس صورت میں قَائِمٌ سے مراد وہ قومیں ہوں گی جن کی نسلیں باقی رہ گئی ہیں.اور حصید سے مراد وہ قومیں جن کی نسلیں بھی اب بالکل یا قریباً نابود ہوگئی ہیں.(۲) خود بستیاں اور اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ بعض شہروں کے نشان ابھی تک موجود
Page 358
ہیں اور بعض کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں.اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی نتیجہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جن قوموں کا پہلے ذکر ہوچکا ہے ان میں سے بعض کے آثار اب تک باقی ہیں اور بعض کے آثار کا پتہ نہیں چلتا.اس صورت میں اگر بعض بستیوں کے آثار نہ ملیں تو یوروپ والوں کو یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ قرآن مجید کی بات غلط ہے کیونکہ قرآن کریم تو خود کہتا ہے کہ بعض ان میں سے بے نشان ہوچکی ہیں.ہاں اگر مل جاویں تو پھر بھی قرآن مجید پر کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا.کیونکہ حَصِیْدٌ کے ایک معنے درانتی سے کٹے ہوئے کے بھی ہوتے ہیں.اور درانتی سے کاٹنے کی صورت میں جڑیں باقی رہ جاتی ہیں.پس اگر مٹے ہوئے نشان مل بھی جائیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا.وَ مَا ظَلَمْنٰهُمْ وَ لٰكِنْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اور ہم نے ان پر (کوئی) ظلم نہیں کیا (تھا) بلکہ انہوں نے (خود ہی) اپنی جانوں پر ظلم کیا.پھر جب تیرے رب کا اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا (عذاب کا) حکم آگیاتو ان کے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ (تعالیٰ) کے سوا پکارا کرتے تھے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ١ؕ وَ مَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ۰۰۱۰۲ اور سوائے تباہی میں ڈالنے کے انہوں نے( کسی بات میں) انہیں نہ بڑھایا.حلّ لُغَات.تَتْبِیْبٌ تَبَّبَہٗ اَھْلَکَہٗ.اسے ہلاک کر دیا.(اقرب) تفسیر.سزا اعمال بد کا نتیجہ ہے قرآن مجید متواتر اس بات پر زور دیتا ہے کہ جن لوگوں کو بھی ہم نے سزا دی ہے اس سزا کا باعث خود ان کے اعمال تھے.ہماری طرف سے ظلماً یہ بات صادر نہیں ہوئی.اس طرح زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آئندہ تقدیر کے مسئلہ کے ماتحت خدا تعالیٰ پر ظلم کا الزام لگایا جائے گا.قریباً ہر مقام پر جہاں جہاں سزا کا ذکر آیا ہے یہ مضمون ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے.گویا خدا تعالیٰ اس قسم کی تقدیر سے انکار کرتا ہے کہ وہ بلاوجہ ایک قوم کو ترقی دیتا اور دوسری کو تباہ کر دیتا ہے.قرآن کریم کے الفاظ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ عذاب اور سزائیں سزایافتہ لوگوں کے افعال و اعمال کا مناسب حال اور طبعی نتیجہ تھیں.مَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمْ کے معنی مَاۤ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُم سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ دوسری چیزیں
Page 359
مثلاً آگ پانی ہوا وغیرہ تو ان کو نفع دے جاتی ہیں مگر ان کے معبود ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کفار کی تلواروں نے تو بعض صحابہ کو شہید بھی کیا مگر مکہ کے بتوں نے تو کچھ نہ کیا.فرمایا یہ عجیب بیوقوفی ہے کہ جو چیزیں کوئی بھی نفع نہیں دیتیں ان کو یہ لوگ خدا بناتے ہیں.بتوں کی حقیقت الٰہی فیصلہ صادر ہونے پر ظاہر ہوگی لَمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَسے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اصل حقیقت اسی وقت ظاہر ہوسکتی ہے جب خدا تعالیٰ بتوں کا پول کھولنے کا فیصلہ کرے.ورنہ اس سے پہلے پہلے تو کئی قسم کے فوائد لوگ معبودانِ باطلہ کی طرف منسوب کرتے رہتے ہیں.مگر جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجاتا ہے تو پھر کسی کے بنائے کچھ نہیں بنتی اور شرک کی حقیقت کھل جاتی ہے.بت کن معنوں میں کوئی ضرر نہیں پہنچاتے قرآن مجید ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ بت ان کو نہ کوئی ضرر پہنچاتے ہیں نہ نفع.مگر مَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍسے معلوم ہوتا ہے کہ بت ضرر پہنچا سکتے ہیں.سو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیےکہ ضرر دو قسم کا ہوتا ہے.ایک اختیاری ضرر ہوتا ہے جیسے کوئی انسان جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچائے اور ایک بلا اختیار جیسے کوئی مکان گر جائے اور اس کے نیچے کوئی دب جائے جس میں اس مکان کے ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا.بلکہ اس کے ایک طبعی فعل کا ایک طبعی نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے.جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے.ان دونوں قسم کے نقصانوں کو سمجھ لینے کے بعد اس بات کا سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ جس جگہ قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ غیراللہ معبود کوئی ضرر نہیں پہنچاسکتے اس جگہ ضرر سے مراد پہلی قسم کا ضرر ہے.اور جس جگہ یہ فرمایا ہے کہ ان سے تعلق ہلاکت کا موجب ہوتا ہے وہاں دوسری قسم کا ضرر مراد ہے.اور اس میں کیا شک ہے کہ بلاارادہ ضرر تو سب سے زیادہ معبودان باطل سے ہی پہنچتا ہے.کیونکہ سب سے بڑا جرم شرک ہی ہے.فتح مکہ کے وقت جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں اشرار کو پناہ نہیں دی جاوے گی تو وہ لوگ دوڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف کو چمٹ گئے.اور اس کے اندر چھپ گئے.مگر وہ وہیں مارے گئے(السیرۃ الحلبیۃ الجزء الثالث زیر عنوان فتح مکۃ).اگر ان کو یہ خیال نہ ہوتا کہ بت ان کی کوئی مدد کریں گے تو ممکن تھا کہ بھاگ کر بچ جاتے.پس غَیْرَتَتْبِیْبٍ میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ شرک کی وجہ سے مشرکوں کی تدابیر میں سستی آجاتی ہے.
Page 360
وَ كَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الْقُرٰى وَ هِيَ ظَالِمَةٌ١ؕ اِنَّ اور تیرے رب کی گرفت جب وہ بستیوں کو اس حالت میں کہ وہ ظلم (پر ظلم )کر رہی ہوں پکڑتا ہے اسی طرح پر اَخْذَهٗۤ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ۰۰۱۰۳ (اتمام حجت کے بعد )ہوا کرتی ہے.اس کی گرفت یقیناً دردناک (اور) سخت ہوتی ہے.تفسیر.اس آیت میں ان تمام واقعات کے بیان کرنے کی غرض بتائی ہے.جو اس سے پہلے بیان ہوچکے ہیں.اور بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو اس کے نام و نشان تک کو مٹا دیتا ہے.اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہوشیار ہوجانا چاہیےاور ایسے طریق اختیار نہیں کرنے چاہئیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ان پر کھینچ لائیں.ظلم کے معنی شرک اس آیت میں ظَالِمَۃٌ کے معنی مُشْرِکَۃٌ کے ہیں اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں متعدد جگہ استعمال ہوا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی ثابت ہیں (بخاری کتاب التفسیر سورۃ لقمان باب لا تشرکوا باللہ ان الشرک لظلم عظیم )اور مراد یہ ہے کہ جس وقت کسی قوم میں سے حقیقی توحید مٹ جاتی ہے اس وقت اس پر جو عذاب آتا ہے وہ بہت زیادہ تباہی کا موجب ہوتا ہے اور جو تباہی طبعی اسباب تنزل کے ماتحت آتی ہے وہ آہستہ آہستہ آتی ہے.اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ١ؕ ذٰلِكَ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو اس کے لئے( خدا تعالیٰ کی)اس ( گرفت) میں یقیناً یقیناً ایک (عبرت انگیز ) يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ١ۙ لَّهُ النَّاسُ وَ ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ۰۰۱۰۴ نشان (پایا جاتا) ہے یہ ایک ایسا دن( آنے والا) ہے جس کے لئےلوگوں کو جمع کیا جائے گا.اور یہ آمنے سامنے ہو نے کا دن ہو گا.تفسیر.قیدلِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِاور اس کے معنی اس آیت کے متعلق یہ سوال
Page 361
ہوسکتا ہے کہ جب نشان کو دیکھ کر وہی شخص آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے جو پہلے ہی اس سے ڈرنے والا ہوتا ہے.اور جو پہلے سے ڈرنے والا نہیں ہوتا وہ اس نشان کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتا تو اس صورت میں اس عذاب کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سوال کے جواب میں یاد رکھنا چاہیےکہ یہاں آیت سے مراد قیامت کا ثبوت نہیں ہے.بلکہ اس کا نصیحت کا موجب بننا مراد ہے.اور اس میں کیا شک ہے کہ قیامت سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرسکتے ہیں کہ جو اخروی عذاب پر ایمان رکھتے ہوں.پس چونکہ اس جگہ سے مضمون مومنوں کی طرف پھرنے والا تھا.اس لئے فرمایا کہ عذابوں کو دیکھ کر ان کے دل میں آخرت کے عذاب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے.اور وہ خشیت کی وجہ سے اگلے جہان کے لئے اور زیادہ محنت اور کوشش شروع کردیتے ہیں.یعنی وہ دنیوی سزا کو دیکھ کر اس پر اخروی عذاب کو قیاس کرلیتے ہیں.مَجْمُوْعٌ١ۙ لَّهُ النَّاسُ کے معنی مَجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ.لوگ اس دن کی خاطر جمع کئے جائیں گے.مطلب یہ کہ وہ دن اپنی ذات میں انسانی تکمیل کے لئے ضروری ہے اس وجہ سے وہ کسی اور مقصد کا ذریعہ نہیں بلکہ خود مقصود ہے.اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مقررہ دن میں کل مخلوق کو جمع کرنا بلا سبب نہیں اور نہ اتفاقاً ہے.بلکہ خاص مقصد کے ماتحت ہے.اور بالارادہ ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس دن ہر اک چیز نمایاں ہوجائے گی.اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا کوئی فعل بھی اس کا خالص ذاتی فعل نہیں ہوتا بلکہ تمام انسانی افعال پہلے انسانوں یا پہلے حالات یا اپنے ہم صحبتوں یا ان کے حالات اور اپنے بعد آنے والوں اور ان کے حالات سے متاثر ہوتے ہیں.اور ہر فعل کے اچھا یا برا قرار دینے میں یا زیادہ یا کم اچھا یا برا قرار دیتے وقت ان حالات اور تاثیروں کا لحاظ ضروری ہوتا ہے.مثلاً ایک انسان جرم کا عادی ہو.لیکن اس کے جرم میں اس کے دماغ کی بناوٹ کا دخل ہو جو بناوٹ اسے کسی پچھلے بزرگ سے جو مجنون یا نیم مجنون ہو ورثہ میں ملی ہو اس صورت میں اس مجرم کے افعال کا اندازہ خود اس کے اپنے افعال کو دیکھ کر نہیں لگایا جاسکتا.جب تک اس کے مورث اعلیٰ کی دماغی حالت ہمارے سامنے نہ ہو.ہم اس کے افعال کی قیمت لگانے میں ضرور غلطی کریں گے.پس انسانی اعمال کی حقیقت کے پورے انکشاف کے لئے اور دوسرے لوگوں کو یہ تسلی دلانے کے لئے کہ مختلف انسانوں کی سزا اور جزا میں جو بظاہر غیر واجب تفاوت نظر آتا ہے وہ تفاوت ظلماً نہیں بلکہ ان کے صاحب اختیار ہونے یا نہ ہونے کے سبب سے ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ جس میں سب کے سب بنی نوع انسان اپنے تمام حالات سمیت جمع ہوں تاکہ ہر اک شخص کے تمام افعال کے علل و اسباب نظروں کے سامنے ہوں اور سزا اور جزا کے وقت اس کو بھی اور دوسروں کو بھی معلوم ہوجائے کہ سزا یا جزا دیتے وقت پورے انصاف سے کام لیا گیا ہے.
Page 362
وَ مَا نُؤَخِّرُهٗٓاِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍؕ۰۰۱۰۵ اور ہم اسے صرف ایک گنی ہوئی میعاد تک پیچھے ڈال رہے ہیں.حلّ لُغَات.لَام جَارَّہ لِلَامِ الـجَارَّۃِ اِثْنَانِ وَعِشْرُوْنَ مَعْنًی.لَامِ جَارَّہ کے بائیس معنی ہیں.الثَّامِنُ مُوَافَقَۃُ اِلٰی آٹھویں معنے اس کے الی والے ہیں یعنی ’’تک‘‘ (اقرب) تفسیر.کون سی اجل ٹل سکتی ہے اور کون سی نہیں ٹل سکتی اجل دو قسم کی ہوا کرتی ہے.(۱) جو ٹل سکتی ہے (۲) جو ٹل نہیں سکتی.جو اجل ٹل سکتی ہے اس کے لئے ایک دائرہ مقرر ہوتا ہے.وہ اس دائرہ سے تو آگے پیچھے نہیں ہوسکتی مگر اس کے اندر حالات کے ماتحت گھٹ بڑھ سکتی ہے.جیسے انسانی عمر کا دائرہ ہے.ایک مقررہ میعاد کے اندر تو کمی بیشی ہوسکتی ہے مگر اس میعاد سے آگے پیچھے نہیں ہوسکتی وہ اجل جو کسی صورت میں نہیں ٹل سکتی وہ دنیا کی تباہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.وہ مقرر ہے معدود ہے اور اٹل ہے.يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ١ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّ جس وقت وہ آئے گی کوئی شخص اس (خدائے برتر) کے اذن کے سوا کلام نہیں کر سکے گا.پھر ان میں سے( بعض) سَعِيْدٌ۰۰۱۰۶ بد بخت (ثابت) ہوں گے اور( بعض) خوش نصیب.تفسیر.اِلَّا بِاِذْنِهٖکے معنی اِلَّا بِاِذْنِهٖ یعنی وہ جزا کا وقت ہوگا اور اس وقت عدالت قائم کی جائے گی اور بجز اذن الٰہی کے کوئی کلام نہیں کرے گا.یہ مطلب نہیں کہ جس طرح اس دنیا کی عدالتوں میں افسر مجاز سے اجازت حاصل کئے بغیر بولنے کی اجازت نہیں ہوتی اگلے جہان میں بھی ایسا ہی ہوگا.کیونکہ اس دنیا میں تو اس لئے اجازت نہیں ہوتی کہ ایک ہی وقت میں کئی آدمی بول کر شور نہ ڈال دیں.مگر خدا تعالیٰ کے سامنے یہ دقت نہیں ہے.پس مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر ارشاد الٰہی کے بولے گا ہی نہیں.کیونکہ ہر اک نفس جانتا ہوگا کہ عالم الغیب خدا کے سامنے کچھ عذر پیش کرنا فضول ہے.مگر اللہ تعالیٰ اپنے کامل رحم سے کام لے کر خود لوگوں کی وکالت کرے گا.اور انہیں ان امور کو سامنے لانے کا ارشاد فرمائے گا جو ان کی ذات کے لئے یا ان کے ساتھیوں کی ذات کے لئے جرم کی
Page 363
تخفیف یا نیکی کی عظمت ظاہر کرنے کا موجب ہوں.فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّ سَعِيْدٌ.شقی وہ ہے جس کے اندر نیکی کا مادہ نہ ہو اور اس کا قلب نیکی کی تحریک سے متاثر نہ ہو.اور سعید وہ ہے جس میں نیکی کا مادہ ہو اور نیکی کی تحریک سے متاثر ہونے والا ہو.اس دن شقی کی اہانت اور سعید کا اعزاز ظاہر کیا جائے گا.فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ پس جو بد بخت (ثابت )ہوں گے وہ آگ میں (داخل) ہوں گے اس میں (کسی وقت )ان کے لمبے سانس( نکل وَّشَهِيْقٌۙ۰۰۱۰۷ رہے )ہوں گے اور( کسی وقت) ہچکی کی حالت کے سانس.حلّ لُغَات.زَفِیْرٌ زَفِیْرٌمصدر ہے زَفَرَ.یَزْفِرُ.زَفْرًا.وَزَفِیْرًا.اَخْرَجَ نَفْسَہٗ بَعْدَ مَدِّہٖ اِیَّاہُ.لمبا سانس کھینچ کر ہوا باہر نکالی.اَلنَّارُ سُمِعَ صَوْتٌ لِتَوَقُّدِھَا آگ زور سے بھڑکی.جس کے شعلوں سے آواز پیدا ہوئی.وَالزَّفِیْرُ.الدَّاھِیَّۃُ.نیز زَفِیْرٌ کے معنی بڑی مصیبت کے ہیں.وَاَوَّلُ صَوْتِ الْحِمَارِ.اور گدھے کی آواز کے پہلے حصے کو یعنی اس کے بولنے کے وقت جو اس کی ایک لمبی آواز پیدا ہوتی ہے اسے بھی زَفِیْرٌ کہتے ہیں.(اقرب) شَہِیْقٌ شَھَقَ الرَّجُلُ یَشْہِقُ شَہِیْقًا تُرَدَّدُ الْبُکَاءُ فِی صَدْرِہٖ.ہچکیاں لے لے کر رویا شَہِیقُ الْحِمَارِ.اٰخِرُ صَوْتِہٖ.گدھے کی آواز کا پچھلا حصہ یعنی جو چھوٹی چھوٹی آوازوں کا مجموعہ آخر میں سنائی دیتا ہے.(اقرب) تفسیر.کفار کی تشبیہ گدھوں سے قرآن مجید نے کفار کے لئے زَفِیْرٌ اور شَہِیْقٌ کے الفاظ استعمال کرکے انہیں گدھے سے مشابہت دی ہے.جس کی ایک وجہ تو قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ بتائی ہے کہ جس طرح گدھے پر کتابیں لاد و تو وہ عالم نہیں ہو جاتا بلکہ ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے اسی طرح صداقت سے غافل لوگ ہوتے ہیں.کہ ظاہری علم تو انہیں حاصل ہوتا ہے لیکن عرفان اور روحانیت سے وہ بالکل خالی ہوتے ہیں.پھر گدھا بے وقوفی کے لحاظ سے بھی مشہور ہے.اور قرآن مجید نے گدھے کی بزدلی کا بھی ذکر فرمایا ہے جیسے آتا ہےكَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ.فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ.(المدثر :۵۱،۵۲) ایسا ہی کافر بھی بزدل ہوتا ہے.اگر ہم غور سے دیکھیں تو ایمان نہ لانے کی دو ہی بڑی وجہیں ہوتی ہیں.(۱) انسان ان علوم سے فائدہ نہیں اٹھاتا جو اس کے سامنے
Page 364
پیش کئے جاتے ہیں.(۲) وہ سچائی کو سمجھ جاتا ہے.مگر خوف کی وجہ سے نہیں مان سکتا اور ان دونوں حالتوں میں کافر انسان گدھے سے مشابہت رکھتا ہے.لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّ شَهِيْقٌ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ آواز دوزخ میں جانے والوں کی ہوگی.پس جن دوسری آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے آواز آئے گی ان سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ دوزخیوں کے رونے اور چلانے کی آواز ہی ہوگی.خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ درانحالیکہ وہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں.سوائے اس (عرصہ) کے جو تیرا رب چاہے رَبُّكَ١ؕ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ۰۰۱۰۸وَ اَمَّا الَّذِيْنَ تیرا رب جو چاہتاہے یقیناً اسے کر کے رہتا ہے.اور جو خوش نصیب (ثابت) ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَ درآنحالیکہ وہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں سوائے اس (وقت) کے جو تیرا رب چاہے.الْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ١ؕ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ۰۰۱۰۹ ( یہ ایسی) عطا ہے جو (کبھی) کاٹی نہیں جائے گی.حلّ لُغَات.سُعِدُوْا.سُعِدُوْا عَلَی الْمَجْھُوْلِ وَسَعِدَ یَسْعَدُ سَعَادَۃً.ضِدّ شَقِیَ.سُعِدَ اور سَعِدَ کے معنی یہ ہیں کہ فلاں شخص میں شقاوت کے خلاف حالت پائی گئی.فَھُوَ مَسْعُوْدٌ عَلَی الْاَوَّلِ وَسَعِیْدٌ عَلَی الثَّانِیَ وَاللُّفْظُ یَأْتِی مَرَّۃً بِصِیْغَۃِ الْفَاعِلِ وَمَرَّۃً بِلَفْظِ الْمَفْعُوْلِ وَالْمَعْنٰی وَاحِدٌ.پس پہلے صیغے یعنی مجہول کے لحاظ سے صاحب سعادت کو مسعود کہتے ہیں.اور دوسرے صیغے یعنی معروف کے لحاظ سے اسے سعید کہتے ہیں.اور اس طرح پر بسا اوقات ایک لفظ کے اسم فاعل اور اسم مفعول ہر دو کے صیغے ہم معنی آتے ہیں اور وہ لفظ دونوں صیغوں میں ایک ہی معنی دیتا ہے.نَحْوَعَبْدٌ مُکَاتِبٌ وَمُکَاتَبٌ وَبَیْتٌ عَامِرٌ وَمَعْمُوْرٌ.جیسے مکاتِبْ (بصیغہ اسم فاعل) اور مُکَاتَبْ (بصیغہ اسم مفعول) اور اسی طرح عامر اور معمور ہم معنی ہیں.وَنَظَائِرُہٗ کَثِیْرَۃٌ.اور اس کی نظائر
Page 365
عربی زبان میں بکثرت پائی جاتی ہیں.اَلسَّعْدُ الْیُمْنُ.سعد کے معنی برکت کے ہیں.اَسْعَدَہٗ عَلَیْہِ اَعَانَہٗ اِسْعَدَ کے معنی ہیں دوسرے شخص کے خلاف اس کی مدد کی.(اقرب) مَجْذُ وْزٌ.جَذَّ میں سے اسم مفعول ہے.جَذَّ الشَّیْ ءَکَسَرَہٗ وَقَطَعَہٗ مُسْتَأْصِلًا.اسے توڑ دیا.ا ور جڑ سے کاٹ دیا.جَذَّ.اَسْرَعَ جلدی سے دوڑا.النَّخْلَ صَرَمَہٗ کھجور کو کاٹ دیا.(اقرب) پس غَیْرَمَجْذُوْذٍ کے معنی ہوئے جو کاٹی نہیں جائے گی.بند نہ ہوگی.تفسیر.نجات کے متعلق اختلاف مذاہب اس آیت میں ایک ایسے مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے جس میں اسلام کو دوسرے تمام مذاہب سے سخت اختلاف ہے اور وہ مسئلہ نجات کا ہے.ہندوؤں کا عقیدہ ہندوؤں کا یہ خیال ہے کہ دوزخ اور جنت (جزا سزا) دونوں ہی محدود ہیں.انسان اپنے اعمال کی جزا یا سزا بھگت کر پھر اسی دنیا میں آجاتا ہے(ستیارتھ پرکاش صفحہ ۵۶۳).اگرچہ ان کے بعض فرقوں کا باہم اختلاف ہے.مگر تمام میں یہ بات بطور بنیاد کے موجود ہے کہ جزا اور سزا ہر دو عارضی ہیں.یہود کا عقیدہ آرین قوم کے علاوہ جن میں سے ہندو ہیں.دوسرا بڑا سلسلۂ اقوام سامی ہے.اس سلسلہ میں یہودی نسلاً اور عیسائی مذہباً شامل ہیں.یہود کے نزدیک جنت غیر یہودی کے لئے بالکل نہیں.اور دوزخ یہودی کے لئے قریباً حرام ہے.زیادہ سے زیادہ ایک یہودی گیارہ مہینے دوزخ میں رہ سکتا ہے(جیوش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Gehennda).اس کے سوا باقی لوگوں کے لئے جہنم ابدی اور غیرمنقطع ہے.عیسائیوں کا عقیدہ عیسائیوں کے نزدیک جہنم بھی غیرمنقطع ہے اور جنت بھی غیرمنقطع(مکاشفہ ۱۱.۹؍۱ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط ۱؍۵).عیسائیوں کے بعض فرقوں کے نزدیک آخرکار جنت مٹ جائے گی.اسلامی تعلیم اسلام ان تمام عقائد سے اختلاف رکھتا ہے.اسلام کی وہ ثابت شدہ تعلیم جسے پہلے بھی اکثر ائمہ مانتے چلے آئے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خصوصیت سے اور نئے رنگ میں اس پر زور دیا ہے.وہ یہی ہے کہ جنت ہمیشہ کے لئے اور غیرمحدود زمانہ تک کے لئے ہے لیکن دوزخ غیرمنقطع نہیں.ایک زمانہ آئے گا کہ دوزخ ختم ہو جائے گا.(ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۲۸۰.۲۸۱).اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَکے معنی مفسرین نے اس اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ کی جو دوزخ کے متعلق آتا ہے تفسیر میں بہت اختلاف کیا ہے.اور مختلف توجیہات بیان کی ہیں(الجامع لاحکام القرآن زیر آیت ھذا).(۱) بعض نے مابمعنی منْ مانا اور اِلَّا مَاشَآء کواِلَّا مَنْ شَآءَ رَبُّكَ قرار دیا ہے.یعنی جسے خدا چاہے گا نکال لے گا.یعنی ان کے نزدیک دوزخ تو غیرمنقطع ہی ہے مگر موحد گنہگار ایک زمانہ کے بعد اس میں سے نکال لئے جائیں
Page 366
گے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مَا مَنْ کے معنی میں بھی آجاتا ہے مگر وہیں آتا ہے جب کہ اس مَنْ میں بعض ما (غیر ذوی العقول چیزیں) بھی شامل ہوں.لیکن اس موقع پر ایسے وجود شامل نہیں ہیں.اس لئے یہ تاویل درست نہیں معلوم ہوتی.بعض اور بواعث کی وجہ سے بھی اس کا استعمال مَنْ کی جگہ جائز ہے.مگر وہ بواعث بھی یہاں موجود نہیں ہیں.ان معنوں کی تائید میں جو بعض مثالیں ما کی ایسی پیش کی گئی ہیں جن سے صرف انسان ہی مراد ہیں.مثلاً مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ (النساء:۴) ان کو محققین نے تسلیم نہیں کیا.بلکہ ان کے نزدیک ما اس قسم کی آیات میں اور معنوں میں آیا ہے.اور یہی درست ہے.موحد گنہگار کے لئے خلود نار کے الفاظ آئے ہیں نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے موحد گناہ گار کے لئے بھی وہی الفاظ استعمال کئے ہیں جو ایک کافر کے لئے.پس فرق کرنے کے لئے کوئی دلیل چاہیےجو موجود نہیں ہے.سورۂ نساء میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نسبت فرماتا ہے کہ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا١۪ وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.(آیت:۱۵) یعنی وہ مسلمان جو اس آیت سے پہلے گذرے ہوئے احکام کو تسلیم نہیں کریں گے.دوزخ میں جائیں گے اور اس میں رہتے ہی چلے جائیں گے اسی طرح اسی سورۃ کے رکوع ۱۳ میں فرماتا ہے وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا(النساء:۹۴).اور جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر قتل کردے.اس کی سزا جہنم ہوگی.وہ اس میں ہمیشہ رہے گا.اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا.ا ور اسے اپنے قرب سے محروم کر دے گا.اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کرے گا.سورۂ جن رکوع ۲ میں ہے وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا (الجن:۲۴).اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے کفار کا ذکر ہے.لیکن اس آیت میں جو قاعدہ بتایا گیا ہے وہ صرف کفار پر چسپاں نہیں ہوتا.بلکہ ہر اک نافرمانی کرنے والے پر خواہ موحد ہو یا غیرموحد پس اس کے حکم کی عمومیت کو ہم کسی صورت میں مقید نہیں کرسکتے.جہنم میں داخل ہونے سے قبل کا زمانہ مستثنیٰ نہیں ہو سکتا (۲)بعض نے کہا ہے کہ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ سے مراد دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے(تفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت ھذا).یعنی اِلَّاالْوَقْتُ الَّذِیْ لَایُدْخِلُہُمْ اللہُ فِی النَّارِ.اَیْ قَبْلَ مَایُدْخِلُھُمْ فِی النَّارِ.لیکن یہ معنی بھی نہیں ہوسکتے کیونکہ اس سے پہلے خَالِدِیْنَ فِیْھَا آچکا ہے اور اِلَّا خُلُوْد کے زمانہ سے ہی اپنے بعد والے مضمون کا استثناء کرتا ہے.اور یہ استثناء اسی صورت میں درست ہوسکتا ہے جبکہ مستثنیٰ وجودوں کا پہلے دوزخ میں داخلہ مان لیا جائے نیز خلود سے آئندہ کا زمانہ مراد
Page 367
ہوتا ہے.نہ کہ پچھلا.جیسا کہ فرمایا اَفَاۡىِٕنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ.(الانبیاء :۳۵) اگر پہلا زمانہ بھی خلود کے منافی ہوتا تو وہ تو آہی چکا تھا.اور وہ پیدا ہوچکے تھے.پس خلود کی نفی تو پیدائش ہی سے ہوجاتی تھی.اہل جنت کے متعلق یہی استثناء جنتیوں کے متعلق جو استثناء ہے اس کے متعلق بھی بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے اعراف والے لوگ یا دوزخ سے نکل کر جنت میں آنے والے لوگ اور ان کا زمانہ مراد ہے.اس کا بھی یہی جواب ہے کہ خلود بعد کے زمانہ کے امتداد پر دلالت کرتا ہے.نہ کہ پہلے زمانہ کے امتداد پر.عذاب جہنم غیر منقطع نہیں اصل میں ساری مشکل ان لوگوں کو اس وجہ سے پیش آئی کہ اس آیت کے الفاظ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ دوزخ کا عذاب آخر ختم ہونے والا ہے لیکن ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دوزخ کا عذاب بھی جنت کی نعماء کی طرح غیرمجذوذ اور نہ ختم ہونے والا ہے.اس لئے وہ ان توجیہات پر مجبور ہوئے.حدیث سے اس مدعا کا اثبات حالانکہ حق یہ ہے کہ نہ صرف قرآن مجید ہی دوزخ کو منقطع قرار دیتا ہے بلکہ احادیث بھی اسی کی تائید کرتی ہیں.چنانچہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی روایت سے احمد (ابن حنبل) نے نقل کیا ہے کہ لَیَأْتِیَنَّ عَلٰی جَھَنَّمَ یَوْمٌ تَصْفِقُ فِیْہِ اَبْوَابُھَا لَیْسَ فِیْہَا اَحَدٌ.وَذٰلِکَ بَعْدَ مَایَلْبِثُوْنَ فِیْہَا اَحْقَابًا (فتح البیان سورۂ ہود آیت زیربحث) ضرور جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے دروازے بجیں گے اور اس میں کوئی شخص نہ ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ لوگ کئی صدیاں اس میں رہ چکے ہوں گے.گویا خلود سے مراد صدیوں رہنا ہے.اس حدیث کے متعلق بعض محدثین کہتے ہیں کہ اس کے راویوں میں ایک کذاب ہے.لیکن یہ اعتراض ان کا درست نہیں کیونکہ یہ روایت قرآن کریم کے مطابق ہے.سورہ نباء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہےلٰبِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا(النباء:۲۴).کہ کفار دوزخ میں صدیوں رہیں گے.سلف صالحین کے اقوال اس بارہ میں فتح البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہی قول ابن مسعودؓ اور ابوہریرہؓ کا بھی ہے اور کئی راویوں سے مروی ہے.اور امام ابن تیمیہ ؓ فرماتے ہیں کہ یہی عقیدہ حضرت عمرؓ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت انسؓ اور بہت سے گزشتہ مفسرین کا بھی تھا.حافظ ابن القیم جو بڑے صوفی اور امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنی کتاب ہَادِیُ الْاَرْواحِ اِلیٰ بِلَادِ الْاَفْرَاحِ میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے(فتح البیان زیر آیت ھذا).بعض ائمہ نے خَالِدِیْنَ کے لفظ کا یہ جواب دیا ہے کہ بے شک وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ دوزخ کو ہی مٹا دے گا اور اس طرح سے اپنا رحم جاری کرے گا تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا.یعنی جب دوزخ ہی نہ رہے گا تو دوزخی اس میں کس طرح رہ سکتے ہیں.علامہ ابن تیمیہ اور ابن القیمؓ
Page 368
نے بھی دوزخ کے فنا ہوجانے کے مسئلہ کی تائید کی ہے.(فتح البیان زیر آیت ھذا) علّامہ بغوی نے اوپر والی روایت حضرت ابوہریرہؓ سے نقل کی ہے.جس سے اس روایت کی مزید تصدیق ہوجاتی ہے.ابن جریر نے شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ جَھَنَّمُ اَسْرَعُ الدَّارَیْنِ عُمْرًانَا وَاَسَرَ عُہُمَا خَرَابًا (تفسیر ابن جریر زیرآیت ھذا).یعنی جہنم دونوں گھروں سے پہلے آباد ہونے والی اور پہلے خراب ہونے والی ہے.وَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍؓ لَیَاتِیَنَّ عَلَیْہَا زَمَانٌ تَخْفُقُ اَبْوَابُہَا.یہی قول جابرؓ ابوسعید خدری اور عبداللہ بن عمرؓ کی طرف سے بھی مروی ہے.(فتح البیانزیر آیت ھٰذا) حدیث شفاعت حضرت ابوسعیدخدریؓ کی بھی ایک روایت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے.اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لئے نہیں ہے.حدیث لمبی ہے اس کا وہ ٹکڑا جس سے استدلال ہوسکتا ہے یہ ہے کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو شفاعت کی اجازت دے گا.آخر مومنوں کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی.پہلے وہ اپنے جان پہچان والے لوگوں کو بچائیں گے.اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی نیکی ہو اسے نکال لاؤ.پھر نصف دینار کے برابر نیکی والوں کو پھر جس کے دل میں ایک ذرہ بھی نیکی ہوگی اس کو بھی نکلوالے گا.اس کے بعد مومن کہیں گے کہ رَبَّنَالَمْ نَذَرْ فِیْھَا خَیْرًا...فَیَقُوْلُ اللہُ شَفَعَتِ الْمَلَٓائِکَۃُ وَشَفَعَ النَّبِیُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَمْ یَبْقَ اِلَّااَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ.فَیَقْبِضُ قَبْضَۃً مِّنَ النَّارِ فَیُخْرِجُ مِنْہَا قَوْمًا لَمْ یَعْمَلُوْا خَیْرًا قَطُّ( مسلم کتاب الایمان باب معرفۃ طریق الرؤیۃ).یعنی اے ہمارے رب! ہم نے دوزخ میں نیکی کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑا.تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ملائکہ نے بھی شفاعت کرلی اور نبیوں نے بھی کرلی اور مومنوں نے بھی کرلی.اور صرف اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ باقی رہ گیا ہے.اس پر خدا تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھرے گا اور دوزخ سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا ہوگا.اس روایت سے ظاہر ہے کہ دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لئے جائیں گے کہ جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی ہوگی اور اس درجہ سے ادنیٰ درجہ کوئی ہے ہی نہیں.کہ جس کی نسبت ہم خیال کریں کہ وہ دوزخ میں رہ گیا ہوگا.نیزاس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر دوزخ سے نکال لے گا.اور خدا تعالیٰ کی مٹھی سے مراد جسمانی مٹھی تو ہے نہیں اس سے مراد احاطہ ہی ہوتا ہے.اور خدا تعالیٰ کے احاطہ سے کون شئے باہر رہ سکتی ہے.تیسرا استدلال اس روایت سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو سزا ملنی ہوگی ان کو ان کی بدیوں کی سزا پہلے مل جائے گی اور خیر کو باقی رکھ لیا جائے گا.اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ (الزلزال:۸) جس نے
Page 369
ایک ذرہ نیکی بھی کی ہوگی وہ اسے ضرور دیکھے گا.پس بعد میں نجات کا ملنا ضروری ہوا.قرآن کریم عذاب جہنم کو منقطع بتاتاہے ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ اور بزرگ تابعین اس مسئلہ میں ہمارے ساتھ ہیں.اور خود قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے.(۱) پہلا ثبوت پہلا ثبوت خود یہی آیت ہے.اس جگہ پر دوزخ اور جنت دونوں کے لئے ایک ہی لفظ ’’اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ‘‘ وارد ہوا ہے مگر دوزخیوں کے متعلق آگے فرمایا ’’اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ‘‘ اور جنت کے ذکر میں ’’اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ‘‘ کے بعد ’’عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ‘‘ فرمایا.’’اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ‘‘ میں زور دے کر بتلایا ہے کہ دوزخیوں کو دوزخ سے ضرور نکالا جائے گا.پہلے اِنَّ کا لفظ رکھا پھر رَبَّ کا لفظ پھر فَعَّالٌ کا لفظ جو کہ مبالغہ کا لفظ ہے اور پھر اس جملہ کو جملہ اسمیہ کے رنگ میں لاکر اور بھی تاکید کردی.اگر ان کو نکالنا ہی نہ تھا تو پھر اتنا زور دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر جیسا کہ جنت کے لئے ’’عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ ‘‘ رکھا ہے اگر دوزخ بھی اسی طرح سے غیرمنقطع تھی تو اس کے متعلق بھی ’’عِقَابًا غَیْرَمَجْذُوْذٍ‘‘ آجاتا.جنت کے متعلق تو فرمایا کہ وہ رہیں گے تو ہماری مرضی کے مطابق مگر ہماری مرضی یہی ہے کہ ہمیشہ رہیں.لیکن دوزخ کے متعلق ایسا مضمون کسی جگہ نہیں فرمایا.یہ بات اتنی واضح ہے کہ ابن حجر جو اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کے خلاف ہیں انہیں بھی کہنا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق تو اپنی مشیت بتادی مگر دوزخیوں کے متعلق خاموش رہا ہے.خاموشی کا دعویٰ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ نے تواِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ فرماکر بتلا دیا ہے کہ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ میں جس طرف اشارہ کیا گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرکے رہے گا.(۲) دوسرا ثبوت.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ.اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ١ؕ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ (ھود:۱۱۹،۱۲۰) اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو امت واحدہ بنادیتا مگر وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے.سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم کرے اور اس نے ان لوگوں کو رحم کے لئے ہی پیدا کیا ہے.وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ کے معنی وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ سے رحم ہی مراد ہے.ابن کثیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے لِلرَّحْمَۃِ خَلَقَھُمْ وَلَمْ یَخْلُقْھُمْ لِلْعَذَابِ (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ولو شاء ربک لجعل الناس..) کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے لئے ہی بندوں کو پیدا کیا ہے اور عذاب کے لئے نہیں پیدا کیا.اور ابن وہب نے طاؤس کے متعلق روایت کی ہے کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے.طاؤس نے انہیں کہا کہ تم کیوں جھگڑتے ہو.ایک نے ان میں سے کہا لِذَالِکَ خُلِقْنَا.یعنی خدا نے ہمیں جھگڑنے اور اختلاف کرنے کے لئے ہی پیدا کیا ہے.طاؤس
Page 370
نے کہا کذَبْتَ تو نے جھوٹ بولا.اس پر اس نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ انسان اختلاف کے لئے پیدا کئے گئے ہیں مگر طاؤس نے جواب دیا خَلَقَھُمْ لِلرَّحْمَۃِ وَالْجَمَاعَۃِ.یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رحم اور اتفاق کے لئے پیدا کیا ہے.ابن کثیر میں ہے کہ مجاہد، ضحاک او ر قتادہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ ’’ذَالِکَ‘‘ کا اشارہ رحم کی طرف ہے.اور درمنثور میں لکھا ہے کہ ابن جریر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ لِلرَّحْمَۃِ خَلَقَھُمْ.ابن ابی حاتم نے عکرمہ اور قتادہ سے روایت کی ہے کہ ’’ لِلرَّحْمۃِ وَالْعِبَادَۃِ ‘‘ کہ رحمت اور عبادت کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے.اب ظاہر ہے کہ اگر کچھ انسان بھی ہمیشہ ہمیش کے لئے دوزخ میں پڑے رہیں تو ان کی پیدائش رحمت کے لئے قرار نہیں دی جاسکتی.اور اس صورت میں نعوذباللہ یہ آیت غلط ہوجائے گی.(۳) تیسرا ثبوت جنت کے متعلق کئی دوسرے مقامات پر فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی جیسے فرمایا فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.(التین:۷)لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ( انشقاق:۲۶) لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ (حٰمٓ سجدۃ:۹) لیکن دوزخ کے متعلق ایسا کہیں نہیں فرمایا جس سے معلوم ہو کہ جنت کی جزا اور دوزخ کی سزا میں فرق ہے.(۴)چوتھا ثبوت.اعراف ع۱۹ میں فرمایا ہے عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ١ۚ وَ رَحْمَتِيْ وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ١ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ(الاعراف:۱۵۷).میں اپنا عذاب تو جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا.اور میری رحمت ہر اک چیز پر وسیع ہے.پس میں اسے بطور حق کے ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو لوگ کہ ہمارے نشانوں پر ایمان لاتے ہیں.اس آیت سے سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے.عذاب ایک درمیانی چیز ہے.جن کو وہ عذاب دے گا ان کو بھی آخر اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا.عذاب کو محدود لوگوں کے لئے بناکر رحمت کو نہ صرف سب انسانوں بلکہ سب اشیاء کے لئے عام کرنا بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اہلِ دوزخ کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا.ورنہ ’’کُلَّ شَیْءٍ‘‘ غلط ہوجاتا ہے.سورہ مومن میں بھی اس مضمون کی ایک آیت ہے فرماتا ہے ’’رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا.‘‘ (مومن :۸) اے خدا تو ہر چیز کا اپنی رحمت اور علم کے ذریعہ سے احاطہ کئے ہوئے ہے.اب اگر بعض لوگ ہمیشہ کے لئے عذاب میں رہ کر رحمت الٰہی سے محروم ہوسکتے ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہونا چاہیےکہ بعض چیزیں خدا کے علم سے بھی نکل سکیں.کیونکہ علم اور رحمت کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے.مگر یہ امر بالبداہت غلط ہے.پس اسی طرح بعض لوگوں کا رحمت سے ابدی طور پر محروم ہونا بھی بالبداہت غلط ہے.
Page 371
نے کہا کذَبْتَ تو نے جھوٹ بولا.اس پر اس نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ انسان اختلاف کے لئے پیدا کئے گئے ہیں مگر طاؤس نے جواب دیا خَلَقَھُمْ لِلرَّحْمَۃِ وَالْجَمَاعَۃِ.یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رحم اور اتفاق کے لئے پیدا کیا ہے.ابن کثیر میں ہے کہ مجاہد، ضحاک او ر قتادہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ ’’ذَالِکَ‘‘ کا اشارہ رحم کی طرف ہے.اور درمنثور میں لکھا ہے کہ ابن جریر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ لِلرَّحْمَۃِ خَلَقَھُمْ.ابن ابی حاتم نے عکرمہ اور قتادہ سے روایت کی ہے کہ ’’ لِلرَّحْمۃِ وَالْعِبَادَۃِ ‘‘ کہ رحمت اور عبادت کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے.اب ظاہر ہے کہ اگر کچھ انسان بھی ہمیشہ ہمیش کے لئے دوزخ میں پڑے رہیں تو ان کی پیدائش رحمت کے لئے قرار نہیں دی جاسکتی.اور اس صورت میں نعوذباللہ یہ آیت غلط ہوجائے گی.(۳) تیسرا ثبوت جنت کے متعلق کئی دوسرے مقامات پر فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی جیسے فرمایا فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ.(التین:۷)لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ( انشقاق:۲۶) لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ (حٰمٓ سجدۃ:۹) لیکن دوزخ کے متعلق ایسا کہیں نہیں فرمایا جس سے معلوم ہو کہ جنت کی جزا اور دوزخ کی سزا میں فرق ہے.(۴)چوتھا ثبوت.اعراف ع۱۹ میں فرمایا ہے عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ١ۚ وَ رَحْمَتِيْ وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ١ؕ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ(الاعراف:۱۵۷).میں اپنا عذاب تو جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا.اور میری رحمت ہر اک چیز پر وسیع ہے.پس میں اسے بطور حق کے ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو لوگ کہ ہمارے نشانوں پر ایمان لاتے ہیں.اس آیت سے سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے.عذاب ایک درمیانی چیز ہے.جن کو وہ عذاب دے گا ان کو بھی آخر اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا.عذاب کو محدود لوگوں کے لئے بناکر رحمت کو نہ صرف سب انسانوں بلکہ سب اشیاء کے لئے عام کرنا بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اہلِ دوزخ کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا.ورنہ ’’کُلَّ شَیْءٍ‘‘ غلط ہوجاتا ہے.سورہ مومن میں بھی اس مضمون کی ایک آیت ہے فرماتا ہے ’’رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا.‘‘ (مومن :۸) اے خدا تو ہر چیز کا اپنی رحمت اور علم کے ذریعہ سے احاطہ کئے ہوئے ہے.اب اگر بعض لوگ ہمیشہ کے لئے عذاب میں رہ کر رحمت الٰہی سے محروم ہوسکتے ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہونا چاہیےکہ بعض چیزیں خدا کے علم سے بھی نکل سکیں.کیونکہ علم اور رحمت کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے.مگر یہ امر بالبداہت غلط ہے.پس اسی طرح بعض لوگوں کا رحمت سے ابدی طور پر محروم ہونا بھی بالبداہت غلط ہے.
Page 372
ہے کہ جب تک جنت و دوزخ کے آسمان و زمین رہیں گے وہ وہاں رہیں گے اور یہ امر کسی آیت سے ثابت نہیں کہ دوزخ کو فناء نہیں کیا جائے گا.اور جب دوزخ کو فنا کر دیا جائے گا تو دوزخیوں کا دوزخ میں رہنے کا زمانہ بھی ختم ہو جائے گا.فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰؤُلَآءِ١ؕ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا پس( اے مخاطب) جو عبادت یہ( لوگ) کرتے ہیں اس کے (باطل ہونے اور برا پھل لانے کے) متعلق تو کسی كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ١ؕ وَ اِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ شک(و شبہ) میںنہ پڑ.یہ اسی طرح کی عبادت کرتے ہیں جس طرح کی عبادت (ان سے) پہلے ان کے باپ دادے نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍؒ۰۰۱۱۰ کرتے تھے اورہم یقیناً یقینا ًانہیں (بھی) ان کا حصہ پورا پورا دیں گے جس میں سے( ہرگز) کچھ کم نہیں کیا جائے گا.تفسیر.فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ کے معنی فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ کے دو معنے ہیں.(۱) ان کے غیراللہ کو معبود بنانے کے متعلق شک نہ کر یعنے یہ خیال نہ کر کہ کس طرح ممکن ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص غیراللہ کی عبادت شروع کردے کیونکہ جو عقیدہ ورثہ سے انسان کو ملتا ہے اور وہ خود اس پر غور نہیں کرتا اس میں ایسی حماقتوں کا ارتکاب اس سے کچھ بعید نہیں ہوتا.ان معنوں کے رو سے تسلیم کرنا ہوگا کہ مخاطب اس زمانہ کے لوگ ہیں جب شرک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو چکا ہوگا اور چاروں طرف توحید کا خیال پھیل جائے گا.ان معنوں کے لحاظ سے یہ آیت ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ توحید ایسی غالب آجائے گی کہ ایک زمانہ میں لوگوں کو یہ بات ماننی مشکل ہو جائے گی کہ کوئی غیراللہ کی بھی عبادت کرتا ہے.غلبۂ اسلام کے زمانہ میں مرکز اسلام کے رہنے والے لوگوں کا یہی حال ہوگا.لیکن اب بھی کفار کے کئی عقائد جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے لوگوں کے لئے قابل تعجب نظر آتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں.(۲) دوسرے معنے یہ ہوسکتے ہیں کہ اے مخاطب یہ نہ سمجھ لے کہ یہ لوگ سزا سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ پہلوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں.جب ان کو سزا ملی تھی تو یہ کیونکر بچ سکتے ہیں.
Page 373
یہ ما موصولہ ہے یا مصدریہ مِمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِمیں ماموصولہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے اور مصدر یہ بھی.یعنی من اَلَّذِیْنَ یَعْبُدُھُمْ ھٰٓؤلَاءِ اَوْمِنْ عِبَادَتِھِمْ یعنی ان کے معبودوں کے متعلق یا ان کی عبادت کے متعلق شک میں نہ پڑ.یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کے متعلق تجھے شبہ پیدا نہ ہو کہ ممکن ہے انہوں نے ہی کوئی ایسی بات کہی ہو جس سے شرک پیدا ہوا ہو.انہوں نے کچھ نہیں کہا.یہ خیالات ان کے اپنے باپ دادوں کی ایجاد ہیں اور یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ ان کی عبادت کے متعلق شبہ نہ کر.پھر ان معنوں کے بھی دو مطلب ہوسکتے ہیں یہ بھی کہ ان کی عبادت کے متعلق یہ شبہ نہ کر کہ کون ایسا فعل کرسکتا ہے اور یہ بھی کہ یہ مشرکانہ عبادت کرتے ہیں تو انہیں سزا کیوں نہیں ملتی؟ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ حال مؤکدہ ہے.صرف زور دینے کے لئے آیا ہے ورنہ وَفّٰی کے معنے خود پورا پورا دینے کے ہوتے ہیں.پس غیرمنقوص کہہ کر مضمون کی مزید تاکید کردی گئی ہے اور بتایا ہے کہ نہ پہلے لوگ سزا سے بچے ہیں نہ یہ بچیں گے.وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ١ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ اور ہم نے (اختلافات کےمٹانے کے لئے) یقیناً موسیٰ کو( بھی) کتاب (تورات) دی تھی پھر (کچھ مدت کے بعد) سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ١ؕ وَ اِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ اس کے متعلق (بھی )اختلاف کیا گیا.اور اگر وہ( رحمت کے وعدہ والی) بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے مِّنْهُ مُرِيْبٍ۰۰۱۱۱ (سے) آچکی (ہوئی) ہے (مانع) نہ ہوتی تو ان کے درمیان (کبھی کا) فیصلہ کیا جا چکا ہوتا اور اب تو وہ اس( کتاب یعنی قرآن) کے متعلق (بھی) ایک بے چین کر دینے والے شک میں (پڑے ہوئے) ہیں.تفسیر.کلام الٰہی کا نزول ہمیشہ ہوتاہے اور ہوتا رہا ہے اب خاتمہ سورۃ پر اصل مضمون کی طرف پھر اشارہ فرماتا ہے کہ کلام الٰہی ضرور نازل ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے مگر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا.موسیٰ ؑ پر کتاب اتری اور اس کتاب میں ایک اور کتاب کا ذکر تھا مگر لوگوں نے قسم قسم کے شبہات اس میں پیدا کرلئے اور
Page 374
اس کے بدنتائج کو نہ دیکھا حالانکہ ان کا جرم اس قدر عظیم الشان تھا کہ اگر اس سے پہلے ہم ایک فیصلہ نہ کرچکے ہوتے تو انہیں تباہ کردیا جاتا.پہلے کے فیصلے سے مراد وہ فیصلہ جس کا ذکر اس جگہ کیا گیا ہے وہی ہے جس کا ذکر وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ میں (الذاریات :۵۷) اور رَحْـمَتِیْ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ(الاعراف :۱۵۷) میں اور اسی قسم کی متعدد اور آیات میں کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ نے بندہ کو روحانی ترقی دینے کے لئے پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا ہے.پس وہ اسے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا تاکہ لوگ ہدایت سے محروم نہ رہ جائیں.اِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ کے معنے وَ اِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ سے دو امر کی طرف اشارہ ہے.اس طرف بھی کہ جو کتاب شک کو دور کرنے کے لئے آئی تھی وہ ان کی اندرونی بیماریوں کی وجہ سے ان کے لئے شک پیدا کرنے کا موجب ہورہی ہے.اور یہ بھی کہ ہمارے رحم سے بجائے فائدہ اٹھانے کے اور شکر گزار بننے کے یہ لوگ اس قسم کے شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کتاب جھوٹی ہوگی تبھی تو اس کے انکار سے سزا نہیں ملتی.وَ اِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ١ؕ اِنَّهٗ بِمَا اور تیرا رب یقیناً یقینا ً(اور) ضرور ان سب کو ان کے اعمال (کے پھل) پورے( پورے) دے گا (گو ابھی تک يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۰۰۱۱۲ نہیں دیئے )وہ جوکچھ کرتے ہیں اسے وہ یقیناً جانتا ہے.تفسیر.اِنَّ كُلًّا لَّمَّا کے لَمَّا کی تحقیق لغوی اس آیت کے متعلق مفسرین میں معنوی طور پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے.مگر اہل لغت میں تحقیق لفظی کی رو سے اختلاف ہوا ہے.یہ اختلاف لَمَّا کے لفظ کی وجہ سے ہے کیونکہ لَمَّا اس جگہ بظاہر ایسی صورت میں استعمال ہوا ہے جس میں استعمال نہیں ہوا کرتا.لَمَّا کے استعمالات لَمَّا کا استعمال تین طرح ہوتا ہے (اول) مضارع پر آتا ہے اور اسے جزم دیتا ہے اور اس کے معنے ماضی منفی کےکردیتا ہے.جیسے لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ (الجمعۃ:۴) وہ ابھی ان سے نہیں ملے.(دوم) ماضی پر آتا ہے اور دو جملے چاہتا ہے.جن میں سے پہلے جملہ کے مضمون کے پورا ہونے پر دوسرے کا مضمون پورا ہوتا ہے.جیسے یہ کہیں کہ لَمَّا جَاءَ نِیْ اَکْرَمْتُہٗ جب وہ میرے پاس آیا میں نے اس کی عزت کی.ایسے استعمال کے
Page 375
وقت ابن جنی کے نزدیک اس کے معنے حِیْنَ کےہوتے ہیں.اور ابن مالک کے نزدیک اِذْ کے (سوم) حرف استثناء کے طور پر استعمال ہوتا ہے.اور اس صورت میں یہ جملہ اسمیہ پر بھی آتا ہے.جیسے کہ قرآن کریم میں ہے.اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (الطارق:۵) اور ماضی پر بھی آجاتا ہے جو لفظاً تو ماضی ہو لیکن معنیً ماضی نہ ہو جیسے اَنْشُدُکَ بِاللہِ لَمَّا فَعَلْتَ یہاں فَعَلْتَ لفظاً ماضی ہے لیکن معنیً مصدر ہے اور اس سے مراد اِلَّافِعْلَکَ ہے یعنے میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ اس کام کے سوا جو میں تجھ سے چاہتا ہوں اور کام نہ کیجیئو.(دیکھو مغنی اللبیب لابن ہشام) اس آیت میں یہ لفظ بظاہر ان تینوں استعمالات کے خلاف استعمال ہوا ہے.نہ اس کے بعد کوئی مضارع اس کا مجزوم بن کر آیا ہے نہ یہ ماضی پر ظرف بن کر آیا ہے کہ اس کے ساتھ دو جملے آئے ہوں.اور نہ جملہ اسمیہ پر یا صیغہ ماضی بمعنے مصدر پر آیا ہے کہ حرف استثناء کے معنے دیتا ہو.اس آیت میں لَمَّا کے متعلق نحویوں کے مختلف اقوال ان مشکلات کو دیکھ کر نحویوں نے مختلف خیالات دوڑائے ہیں اور مبرد جیسوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لمَّا کا یہ استعمال محاورۂ عرب کے خلاف ہے.اور نسائی نے کہا ہے کہ اس کو میں نہیں سمجھ سکا.ابن جنی نے یہ کہا ہے کہ شاید جس طرح الّا زائد آتا ہے لمّا بھی زائد آتا ہو لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا(روح المعانی زیر آیت ھذا).بعض نے اس لفظ کو مرکب قرار دیا ہے.وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ لمّا ایک لفظ نہیں ہے بلکہ لَمَنْ مَّا ہے ن میم سے تبدیل ہوکر تین میموں کے جمع ہوجانے کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے.لیکن یہ بھی درست نہیں.کیونکہ ایسے میم کو تخفیف کی غرض سے حذف کرنے کا جواز ثابت نہیں ہے.بعض نے کہا ہے کہ اصل میں یہ لفظ لَمَّ سے ہے جس کے معنے جمع کرنے کے ہوتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں آیا ہے اَکْلًالَّمَّا.سب کا سب کھا جاتے ہو.نون تنوین کو وصل کی خاطر اڑادیا گیا اور لمّا پڑھ لیا گیا(مغنی اللبیب، اللام لمّا).لیکن یہ بھی درست نہیں کیونکہ وصل کے موقع پر اسم منصرف سے تنوین کا حذف کرنا بالکل بعید از قیاس ہے.یہ لَمَّا جازمہ ہے ان تمام توجیہات کو دیکھنے کے بعد درست وہی معلوم ہوتا ہے جو ابن حاجب نے کہا ہے اور وہ یہ ہے کہ لمّا اس جگہ پر جازمہ استعمال ہوا ہے اور اس کا فعل محذوف ہو گیا ہے اور یہ عربی زبان کے رو سے جائز ہے.لَمَّا اور لَمَّ کے معنوں میں پانچ فرق نحوی بیان کرتے ہیں اور ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ لَمَّ کے بعد کا فعل حذف نہیں کیا جاسکتا.لیکن لَمَّا کے لفظ کا فعل جب اس پر کوئی دلیل موجود ہو حذف کیا جاسکتا ہے.چنانچہ اس کے ثبوت میں نحوی ایک شعر بھی نقل کرتے ہیں جو یہ ہے ؎
Page 376
فَـجِئْتُ قُبُوْرَھُمْ بَدْأً وَلَمَّا فَنَادَیْتُ الْقُبُوْرَ فَلَمْ یُـجِبْنَہ میں اپنی قوم کے بڑے آدمیوں کے مرنے کے بعد جبکہ ان کی جگہ مجھے بڑا آدمی سمجھا جانے لگا اور ابھی میں فی الواقع بڑا آدمی بنا نہیں تھا ان کی قبروں پر گیا اور انہیں بلایا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا.ابن حاجب کا خیال ہے کہ اس آیت میں بھی لما کا فعل حذف ہو گیا ہے.جو ان کے نزدیک یُہْمَلُوْا ہے.یعنی یہ کفار اپنے اعمال کی پاداش سے سبکدوش اور آزاد نہیں ہوچکے.بلکہ ان کے اعمال کی جزا ابھی انہیں ملنے والی ہے.ابن ہشام امامِ نحو کی تحقیق ابن ہشام مصنف مغنی اللبیب کے نزدیک بھی یہی توجیہہ ٹھیک ہے.لیکن وہ کہتے ہیں کہ محذوف یوفَّوا اَعْمَالَھُمْ نکالا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس جملہ کو محذوف مان کر یہ معنے ہوں گے کہ اب تک تو ان کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں دیا گیا.لیکن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دے گا ضرور.علامہ محمد بن حیان اندلسی مصنف تفسیر بحرمحیط نے بھی اس توجیہہ کو صحیح قرار دیا ہے لیکن لکھا ہے کہ میرے نزدیک محذوف فعل ینقص نکالا جائے تو زیادہ مناسب ہے.اور انہوں نے یوں جملہ بنایا ہے لَمَّا یَنْقُصُ مِنْ جَزَآءِ عَمَلِھِمْ لَیُوَفِّیَنَّھُمْ رَبُّکَ اَعْمَالَھُمْ یعنی سب کے سب لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال کا بدلہ اب تک ضائع نہیں ہوا اور ضرور اللہ تعالیٰ ایک دن انہیں ان کے اعمال کی پوری جزاء دے گا.صحیح توجیہہ یہی ہے کہ یہ لَمَّا جازمہ ہے میرے نزدیک توجیہہ یہی صحیح معلوم ہوتی ہے.باقی سب توجیہات بعید از قیاس ہیں اور گو ان کےپیش کرنے والوں کے علمی رتبہ کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم انہیں کلی طور پر باطل نہ کرسکیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں بہت کچھ تکلف معلوم ہوتا ہے مگر یہ توجیہہ بغیر تکلف کے ہے اور عربی کے ثابت شدہ قاعدہ کے مطابق ہے.باقی رہا محذوف کا سوال سو یہ معمولی سوال ہے.ایسے موقع پر محذوف کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ بقیہ عبارت جس مضمون پر دلالت کرے اسے محذوف نکالا جائے اور تینوں فعل جو تین ائمہ صرف و نحو نے محذوف نکالے ہیں تینوں ہی آپس میں ہم معنے ہیں.اس توجیہہ کے مطابق اس آیت کے معنی اور ان میں سے ہر اک کو ہم اختیار کرسکتے ہیں گو ابن ہشام کے قول کویہ ترجیح حاصل ہے کہ محذوف بھی الفاظ قرآن کے مطابق نکالا گیا ہے.اس محذوف کو اگر ظاہر کیا جائے تو عبارت یوں بنے گی.اِنَّ کُلًّا لَّمَّا یوفَّوْا اعمالھم لَیُوَفِّیَنَّھُمْ رَبُّکَ اَعمالَھم یقیناً یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ اب تک انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ملا.مگر ایک دن ضرور تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے
Page 377
گا.یعنی ان لوگوں کو ہمارے ڈھیل دینے سے دھوکا نہیں کھانا چاہیےکہ وہ سزا سے بچ گئے ہیں وہ سزا سے بچے نہیں ان کے اعمال محفوظ ہیں سزا میں ایک مدت تک ڈھیل ہے مگر وہ دن بھی ضرور آنے والا ہے جب مزید ڈھیل اللہ تعالیٰ نہیں دے گا اور یہ لوگ اپنے اعمال کی پوری سزا بھگتیں گے.فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ وَ لَا تَطْغَوْا١ؕ پس (اے رسول) تو ان (لوگوں) کے سمیت جنہوں نے تیرے ساتھ ہو کر (ہماری طرف سچا) رجوع( اختیار) کیا اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۰۰۱۱۳ ہے( اس طرح پر )جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے سیدھی راہ پر قائم رہ.اور( اے مومنو) تم( اس حکم کی) حد سے نہ بڑھنا جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے یقیناً دیکھتا ہے.حلّ لُغَات.اِسْتَقَامَ اِسْتَقَامَ الْاَمْرُوَاسْتَقَامَ لَہٗ الاَمْرُ اِعْتَدَلَ.اس کے لئے کام ٹھیک اور درست ہو گیا.وَفِی الْقُراٰنِ اِسْتَقِیْمُوْا اِلَیہِ اَیْ اِسْتَقِیْمُوْا فِی التَّوَجُّہِ اِلَیْہِ دُوْنَ الْاٰلِھۃِ اور قرآن کے الفاظ اِسْتَقِیْمُوْا اِلَیْہِ کے معنے یہ ہیں کہ تم باقی تمام معبودوں کو چھوڑ کر اس کی طرف اپنی توجہ کو درست کرو.(اقرب) وَاِسْتِقَامَۃُ الْاِنْسَانِ لُزُوْمُہُ الْمَنْھَجَ الْمُسْتَقِیْمَ (مفردات) اور انسان کے لئے استقامت کا لفظ آئے تو اس کے معنی سیدھے راستہ پر قائم رہنے کے ہیں.طغی طَغَی یَطْغٰی طَغًی وَطُغْیَانًا وَطِغْیَانًا جَاوَزَ الْقَدْرَ وَالْحَدَّ.حد اور اندازہ سے آگے نکل گیا.طَغَی فُلَانٌ اَسْرَفَ فِی الْمَعَاصِیْ وَالظُّلْمِ گناہوں اور ظلم میں حد سے بڑھ گیا.(اقرب) تفسیر.آنحضرت ؐ کی ذمہ داری کی وسعت و عظمت اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اپنی جان ہی کی ذمہ داری نہیں بلکہ آپؐ پر ایمان لانے والوں کی درستی بھی آپؐ کا کام ہے.اور یہی ذمہ داری آپؐ کے جانشینوں اور آپؐ پر ایمان لانے والوں پر ہے.کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے یہ ذمہ داری اس قدر ہے کہ پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے.کمیّت کی رو سے عظمت کمیت کی طرف تو فَاسْتَقِمْ اور وَمَنْ تَابَ مَعَک کے الفاظ اشارہ کرتے ہیں.ہمیشہ بغیر وقفہ کے خدا تعالیٰ کے احکام پر قائم رہنا اور اپنے ساتھیوں کو قائم رکھنا کوئی معمولی بات نہیں.
Page 378
کیفیت کی رو سے عظمت اور اس کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے.جب ہم یہ دیکھیں کہ کیفیت جس کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی نہایت اعلیٰ ہے.کیونکہ فرماتا ہے کہ استقامت اس طرح ہو جس طرح خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے.ایک کمزور انسان کے لئے رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کے بتائے ہوئے احکام کو کماحقہ ادا کرنا کس قدر مشکل ہے.استقامت وہی نافع ہوتی ہے جو فرمان الٰہی کے مطابق ہو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خالی استقامت انسان کو نفع نہیں دے سکتی بلکہ وہ استقامت نفع دیتی ہے جو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ہو.بعض لوگ یہ خیال کرلیتے ہیں کہ چونکہ ہم نماز اور روزہ کے پابند ہیں اس لئے اب ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں.حالانکہ نماز اور روزہ اصل میں مطلوب نہیں ہیں مطلوب تو امر الٰہی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے.یہی نماز اور روزہ جس وقت خدا تعالیٰ کے احکام کے خلاف آجائیں انسان کو شیطان بنادیتے ہیں.جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلتے یا اس کے غروب ہوتے وقت شیطان نماز پڑھتا ہے.یعنی یہ کام شیطانی لوگوں کا ہے(مسلم کتاب المساجد مواضع الصلوۃ باب اوقات الصلوۃ الخمس ).اسی طرح عید کے دن روزہ رکھنے والے کا نام آپؐ نے شیطان رکھا.پس حق یہی ہے کہ جب تک انسان کا رویہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے منشاء کے ماتحت نہ ہو اور اس کے اعمال کا محرک صرف خدا تعالیٰ کی رضاء کا حصول نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث نہیں ہوسکتا.آنحضرت ؐ کے اسوہ کی اتباع کی اہمیت اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے لئے آپؐ کی اتباع اور آپؐ کے اسوہ پر چلنا ضروری ہے.کیونکہ فرماتا ہےفَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَكَ.جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے اس طرح مستقل طور پر اور لزوم کے ساتھ تو عمل کر اور تیرے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ بھی اسی طرح عمل کریں.اس سے معلوم ہوا کہ اصل معیار عمل کا وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقرر کیا گیا تھا.اگر ایسا نہ ہوتا تو مومنوں کے لئے یہ فرماتا کہ وہ اس طرح عمل کریں جس طرح انہیں حکم دیا گیا ہے مگر انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے تابع فرماکر بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنا ہی مومنوں کا کام ہے اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے حصول کے لئے جس قدر بھی انسان کوشش کرے کم ہے.اگرہمارے لئے کوئی اور راہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اپنے درجہ کے مطابق کام کرنا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درجہ کے مطابق مگر یہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس مقام پر کھڑے ہونے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس جگہ پر آپؐ کے اتباع کو کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے.مگر افسوس مسلمانوںکا آج یہ حال ہے کہ خود تو اس مقام پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے
Page 379
نہیں اور اگر کوئی خدا کا بندہ اس مقام کو پالیتا ہے تو اسے کافر و دجال کہنے لگتے ہیں.اِنَّالِلہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ.نیکی وہی کام دیتی ہے جو مناسب وقت بھی ہو كَمَاۤ اُمِرْتَ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو وہی نیکی کام دے سکتی ہے جو وقت کے مناسب ہو.نماز کے وقت ذکر الٰہی اور روزہ کے وقت ایسے کام جو روزہ میں روک ہوں اور جہاد کے وقت روزہ جو جہاد میں سست کرے نفع نہیں دے سکتا.پس انسان کو چاہیےکہ اس امر پر غور کرتا رہے کہ آج کل کون سی نیکی کا زمانہ ہے.اور اسی طرح مختلف اوقات میں ان نیکیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے جو اس وقت کے مناسب حال ہوں.زمانہ اور وقت کے لحاظ سے جو نیکی ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے گی.مجھے تعجب ہے کہ اس آیت کو ایک نادان مفسر نے سورہ نساء کی آیت اُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ الآیۃ کے مطابق قرار دے کر یہ استدلال کیا ہے کہ جس طرح اس آیت کے ماتحت صحابہ خاتم النبیین نہیں بن جاتے اسی طرح سورہ نساء کی آیت سے امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ نہیں کھل جاتا(بیان القرآن زیر آیت ھذا).حالانکہ اس جگہ توبہ میں شمولیت کا ذکر ہے نہ ختم نبوت میں.اب کیا کوئی نادان ہے جو یہ کہے کہ صحابہ تائب نہ تھے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تائب تھے.اگر نہیں بلکہ ہر اک کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ تائب دونو تھے گو مقام توبہ میں فرق تھا تو سورہ نساء میں کیوں یہ معنے نہیں کئے جاسکتے کہ نبوت کا لفظ دونوں گروہوں پر بولا جائے گا.گو نبوت کا درجہ مختلف افراد کا مختلف ہوگا.اس آیت کا اثر آنحضرت ؐ پر اس آیت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اثر کیا تھا وہ تو اس سے ظاہر ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے ھُوْدٌ وَاَخَوَاتُھَا شَیَّبَتْنِیْ قَبْلَ الشَّیْبَ.(ابن مردویہ بحوالہ درمنثور) مجھے ہود اور اس جیسی سورتوں نے قبل از وقت بوڑھا کر دیا ہے.کیونکہ آپؐ دیکھتے تھے کہ آپؐ کے ساتھ توبہ کرنے والے لوگ آپؐ کے زمانہ تک ہی محدود نہ تھے بلکہ آپؐ کے بعد قیامت تک آنے والے تھے.ان لوگوں کی تربیت کی ذمہ داری آپؐ کس طرح اٹھا سکتے تھے.یہ خیال تھا جس نے آپؐ پر اثر کیا اور آپؐ کو بوڑھا کر دیا.مگر آپؐ کا یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اس نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور وعدہ کرلیا کہ میں ہمیشہ تیری امت میں سے ایسے لوگ مبعوث کرتا رہوں گا جو تیرے نقش قدم پر چل کر میرا قرب حاصل کریں گے اور تیری طرف سے اس امت کی اصلاح کریں گے.اس آیت کی رو سے ہمارے لئےاپنے محاسبہ کی ضرورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلہ میں اب ہمیں غور کرنا چاہیےکہ ہم نے کیا کیا ہے ہمارا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ فرض رکھا گیا ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ دوسرے مومنوں کی اصلاح کا بھی فکر کریں.
Page 380
ایک ادنیٰ غور سے یہ بات معلوم ہوسکتی ہے کہ بغیر ایک کامل نظام کے اس حکم پر عمل نہیں ہوسکتا.ایک مومن اپنے پاس کے مومنوں کو تو نصیحت کرسکتا ہے لیکن وہ سب دنیا کے مومنوں کو بغیر نظام کے کس طرح نصیحت کرسکتا ہے.صرف مکمل نظام ہی ہے جس کے ذریعہ سے انسان اپنے گھر بیٹھا سب مسلمانوں کی خبر رکھ سکتا ہے کیونکہ جب وہ نظام کے قیام میں مدد دیتا ہے خواہ روپیہ سے وقت سے قلم سے زبان سے یا دماغ سے تو وہ اس نظام کا ایک حصہ ہو جاتا ہے اور اس نظام کے ذریعہ سے جہاں جہاں بھی کام ہوتا ہے اس میں وہ شریک ہوتا ہے.نظام جماعت احمدیہ اس وقت احمدی جماعت ہی نظام کے ماتحت ہے اور دیکھ لو کہ وہی تبلیغ اسلام دنیا کے مختلف ممالک میں کر رہی ہے.ایک پنجاب کے گاؤں کا زمیندار یا ایک افغانستان کے ایک گوشہ میں بسنے والا افغان جو جغرافیہ سے محض نابلد ہے جب اپنی کمائی کا ایک حصہ خزانہ سلسلہ میں ادا کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے ذاتی فرض کو ادا کرتا ہے بلکہ اس طرح وہ یورپ امریکہ سماٹرا جاوا افریقہ وغیرہ مختلف براعظموں اور ملکوں میں تبلیغ اسلام کا جو کام ہورہا ہے اس میں شریک ہو جاتا ہے اور اس حکم کی ذمہ داری سے ایک حد تک سبکدوش ہو جاتا ہے.اولاد کی تربیت اس آیت میں آئندہ اولاد کی درستی اور اس کی تربیت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے.مگر افسوس ہے کہ اس امر کی طرف بہت کم لوگ توجہ رکھتے ہیں.بیہقی نے شعب الایمان (الجزء الثانی صفحہ ۴۷۲،۴۷۳ ذکر سورۃ ھود)میں ابوعلی سری سے روایت کی ہے کہ ابوعلی نے کہا رَاَیْتُ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِی الْمَنَامِ فَقُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللہِ رُوِیَ عَنْکَ اَنَّکَ قُلْتَ شَیَّبَتْنِیْ ھُوْدٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَاالْذِیْ شَیَّبَکَ مِنْہُ قَصَصُ الْاَنْبِیَاء وَھَلَاکُ الْاُمَمِ قَالَ لَا وَلٰکِنْ قَوْلُہٗ فَاسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ! لوگ کہتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ہے مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا.آپؐ نے فرمایا ہاں! اور میں نے عرض کی کس بات نے آپ ؐ کو بوڑھا کر دیا کیا انبیاء کے قصوں اور امتوں کی ہلاکت نے؟ آپؐ نے فرمایا نہیں بلکہ آیت فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ نے مجھے بوڑھا کر دیا اور دارمی نے اور ابوداؤد نے اپنی مراسیل میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں کعبؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِقْرَءُوْا ھُوْدًا یَوْمَ الجُمعَۃِ سورہ ہود کو جمعہ کے دن پڑھا کرو.اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نظامِ جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کیونکہ جمعہ کا دن بھی اجتماع کا دن ہوتا ہے.
Page 381
کیا عجیب بات ہے کہ جس سورۃ نے رسول اللہ جیسے وسیع القلب پر اتنا اثر ڈالا کہ آپؐ بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے وہ ہم پر کوئی اثر نہ کرے حالانکہ ہمیں آپؐ سے زیادہ ڈرنا چاہیےتھا تاکہ اس کام میں کامیاب ہوں جو ہمارے سامنے ہے.اسلام صرف شخصی کامیابی کوکوئی اہمیت نہیں دیتا اصل بات یہ ہے کہ اسلام محض شخصی کامیابی کا قائل نہیں.اگر ہم ساری قوم کو ہر رنگ میں نہیں بڑھاتے تو گویا ہم کامیاب ہی نہیں ہوئے.لَاتَطْغَوْا میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے.کہ قوم کی خبر نہ لینا ظلم ہے کیونکہ خبر نہ لینے سے بدی پھر عود کر آتی ہے.ایک آدمی کا اعلیٰ مقام تک پہنچ جانا دنیا کے لئے چنداں مفید نہیں.کیونکہ اس کے مرتے ہی وہی ظلمت پھیل جائے گی.کامیابی یہ ہے کہ سب صحیح راستہ کو اختیار کرلیں تاکہ بدی کا سر کچلا جائے مگر افسوس ہے کہ باوجود اس تعلیم کے مسلمان نہ صرف دینی علوم میں پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ دنیاوی علوم اور ترقیات میں بھی بالکل بے خبر ہیں.وہ بنی نوع انسان کی بہبودی میں بھی بہت کم حصہ لیتے ہیں جبکہ دوسری قوموں کے بہادر ہر شعبہ علمی میں ترقی کرنے کی کوشش کررہے ہیں.اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مجموعی کوششوں کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح کہ وہ انفرادی کوششوں کو دیکھتا ہے.وَ لَا تَرْكَنُوْۤا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ١ۙ وَ مَا لَكُمْ اور تم ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم (کا شیوہ اختیار) کیا ہے نہ جھکنا.ورنہ تمہیں (بھی جہنم کی) آگ( کی لپٹ) مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ۰۰۱۱۴ پہنچے گی اور (اس وقت) اللہ کے سوا تمہارے کوئی دوست (مدد گار) نہ ہوں گے اور تمہیں (کسی طرف سے بھی) مدد نہیں ملے گی.حلّ لُغَات.رَکَنَ رَکَنَ اِلَیْہِ یَرْکُنُ وَرَکِنَ یَرْکَنُ رُکُوْنًا.مَالَ اِلَیْہِ وَسَکَنَ اس کی طرف جھک گیا اور قرا ر پا گیا.(اقرب) یہ لفظ باب نَصَرَ یَنْصُرُ اور عَلِمَ یَعْلَمُ سے آتا ہے یعنی رَکَنَ یَرْکُنُ اور رَکِنَ یَرْکَنُ مگر کبھی مَنَعَ یَمْنَعُ کے وزن پر بھی آتا ہے مگر یہ عام قاعدہ کے خلاف ہے کیونکہ جب تک دوسرا یا تیسرا حرف حروف حلقیہ سے نہ ہو تب تک اس وزن پر لفظ نہیں آیا کرتا.اور اس لفظ میں نہ دوسرا حرف حروف حلقیہ میں سے
Page 382
ہے نہ تیسرا حرف.(حروف حلقیہ یہ ہیں ع ھ ح خ غ ء) اس لئے اس وزن کو شاذ کہتے ہیں یعنی عام قاعدہ کے خلاف استعمال ہوا ہے مگر شاذ کے معنے غلط نہیں ہوتے.صرف اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس قسم کے الفاظ عربی زبان میں کم پائے جاتے ہیں.تفسیر.ظالم سے تعلق رکھنے والا بھی سزا میں اس کا شریک ہوگا اس آیت میں یہ قاعدہ بتایا ہے کہ ظالم سے تعلق رکھنے والا خود بھی اس کی سزا میں شریک ہوجائے گا.اور پہلی آیت سے اس کا یہ تعلق ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دوسروں کی نگرانی اور خبرگیری رکھو کہ وہ بھی استقامت پر رہیں.اور یہ ظاہر ہے کہ اگر مومن ایسا نہ کریں گے تو دوسرے لوگ اسقامت کو چھوڑ کر ظالم بن جائیں گے اور سزا کے مستحق ٹھہریں گے.اس لئے اس قاعدہ کی طرف توجہ دلائی کہ جو چیزیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرتی ہیں.پس اگر تم ظالموں کی طرف جھکو گے تو وہ خرابیاں جو ان میں پائی جاتی ہیں وہ تم میں بھی سرایت کر جائیں گی.اور ان کا بگڑنا تمہارا ہی بگڑنا ہوگا.غرض یہ سمجھایا ہے کہ اپنے عزیزوں سے تعلق قطع کرنا بھی ایک قسم کی موت ہے اور اگر وہ ظالم ہوں تو ان سےتعلق رکھنا بھی ایک موت ہے.پس اصل راہ یہی ہے کہ ان کی اصلاح کرو.اور انہیں بگڑنے نہ دو تاکہ تعلق توڑنا بھی نہ پڑے اور ان کا تعلق خرابی کا موجب بھی نہ ہو.ظالم کو ظلم سے روکنا بھی ضروری ہے دوسرے اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ پہلی آیت میں جولَا تَطْغَوْا کہہ کر ہم نے ظلم سے منع کیا تھا تو اس کا صرف یہ مطلب نہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے ظلم نہ کرو.بلکہ ظالم کا کسی رنگ میں ممد ہونا یا اس کا ساتھ دینا بھی ظلم ہی ہے.اور انسان کو سزا کا مستحق بنا دیتا ہے.بہت سے لوگ ہیں کہ جو خود تو ظلم نہیں کرتے مگر دوستوں کے ظلم پر پردہ ڈالتے ہیں اور ان کو سزا سے بچانے کے لئے کوشش کرتے ہیں.انہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے.ظالم کے پاس کسی جائز کام کے لئے جانا ممنوع نہیں ہے لَا تَرْكَنُوْۤا سے یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ظالم کے پاس صرف کسی کام کے لئے جانا سزا کا مستحق نہیں بنا دیتا.بلکہ جب انسان ظالم کے ظالمانہ افعال میں تسکین محسوس کرے اور اس پر نفرت کا اظہار نہ کرے تب سزا کا مستحق ہوتا ہے.
Page 383
وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ١ؕ اِنَّ اور( اے مخاطب) تو دن کی دونوں طرفوں اور( نیز) رات کے (متعدد اور مختلف) اوقات میں عمدگی سے نماز ادا کیا کر.الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ١ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَۚ۰۰۱۱۵ نیکیاں یقیناً بدیوں کو دور کر دیتی ہیں.یہ( تعلیم اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو) یاد رکھنے والوں کے لئے ایک نصیحت ہے.حلّ لُغَات.طَرَفٌ.اَلطَّرَفُ حَرْفُ الشَّیْءِ وَنِہَایَتُہٗ.کسی چیز کا کنارہ اور اس کی حد.اَلنَّاحِیَۃُ پہلو جانب طَائِفَۃٌ مِّنَ الشَّیْءِ.کسی چیز کا حصہ (اقرب) دن کی دونوں طرفوں سے مراد صبح اور شام کے اوقات ہیں.زُلَفٌ زُلَفًاجمع کا صیغہ ہے.اس کا واحد زُلْفَۃٌ ہے.اس کے معنی ہیں اَلْقُرْبَۃُ.قرب.اَلْمَنْزِلَۃُ درجہ الطَّائِفَۃُ مِنْ اَوَّلِ اللَّیْلِ.رات کا پہلا حصہ وَقِیْلَ الزُّلَفُ السَّاعَاتُ الَّتِیْ یَلْتِقیْ بِہَا اللَّیْلُ وَالنَّہَارُ.وہ حصے جن میں دن رات ملتے ہیں یعنی دن اور رات کے شروع اور آخر کے حصے.زلف کہلاتے ہیں.(اقرب) وَقِیْلَ لِمَنازِلِ اللَّیْلُ زُلَفٌ.مطلق رات کے اوقات کو بھی زلف کہتے ہیں.(مفردات) تفسیر.اس آیت کا پہلی آیات سے تعلق اور کامیابی کا گُر اس آیت میں نیکی کا گر بتایا ہے اور اس آیت کا پہلی آیات سے یہ تعلق ہے کہ ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے اتباع کی ذمہ داریاں بتائی گئی تھیں.چونکہ اس قدر ذمہ داریوں کا پورا کرنا انسانی طاقت سے بالا تھا.اس لئے اس آیت میں وہ طریق بتایا جس کے ذریعہ سے اس عظیم الشان فرض کے پورا کرنے میں مسلمان کامیاب ہوسکیں وہ گر یہ ہے.کامیابی کا بڑا گُر عبادت الٰہی اور دعا ہے عبادت کرو.اور دعاؤں میں مشغول ہوجاؤ.کیونکہ خدا کی مدد سے ہی یہ کام کرسکو گے اور دوسرے یہ کہ نیک نمونہ سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرو.الفاظ بدیوں کو نہیں مٹا سکتے.بلکہ نیکیاں انہیں مٹاتی ہیں.نیک تقدیر پیدا کرنے کا گُر خود نیک نمونہ دکھاؤ اَقِمِ الصَّلٰوةَ میں نیک تقدیر پیدا کرنے کا گر بتایا ہے اور اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ میں ان تدابیر کا ذکر کیا ہے جن سے بدیاں مٹائی جاسکتی ہیں.ایک تدبیر اس آیت سے یہ نکلتی ہے کہ خود نیک نمونہ دکھاؤ لوگ تمہاری نقل کریں گے.اس طرح قوم کی بدیاں دور ہوتی جائیں گی.اگر ہم ذرہ غور سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے بہت کم لوگ اپنے لئے سوچ کر راستہ تیار کرتے ہیں.سوائے
Page 384
انبیاء کے زمانہ کے کہ ان کے اتباع میں سے کثرت ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہوں نے خود غورکرکے اپنے لئے راستہ تیار کیا ہوتا ہے.باقی زمانوں میں عام طور پر لوگ دوسروں کی نقل کررہے ہوتے ہیں.پس اچھا نمونہ قائم کرنا ایک بہت بڑا ذریعہ نیکی کے قائم کرنے کا ہے.ایسے آدمی کے گردوپیش رہنے والے لوگ ضرور اس کی نقل کرتے ہیں اور اس طرح خودبخود ایک طبقہ بداعمال سے نجات پا جاتا ہے.دوسرا گُر قوم کو وعظ و نصیحت کرنا ہے دوسری تدبیر یہ نکلتی ہے کہ قوم کو وعظ و نصیحت کرو.اس سے بھی بدیاں دور ہوں گی اس صورت میں حسنات کے معنے اچھی باتوں کے کئے جائیں گے.تیسری تدبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں سے حسنِ سلوک کا معاملہ کرو.اس سے شرارت مٹتی ہے.جب لوگوں سے نیک معاملہ کرو گے تو ان کو بھی تم سے محبت پیدا ہوگی.اور وہ تمہاری باتوں کو قبول کریں گے.اس آیت سے ذاتی ترقی کے بھی دو گر معلوم ہوتے ہیں.(۱) ایک تو یہ کہ نیکیوں کی عادت سے بدیوں کی عادت دور ہوتی جاتی ہے.اس لئے جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہے اسے چاہیےکہ جس بدی کی عادت ہو اس کے بالمقابل کی نیکیوں کی عادت ڈالے.اس سے خودبخود اس کی وہ بدیاں جن کی اسے عادت ہو چھوٹنے لگ جائیں گے.(۲) دوسرا گر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو گناہ انسان کر چکا ہو ان کے بد نتائج سے بچنے کا ذریعہ نیکی میں ترقی کرنا ہے.جتنا جتنا وہ نیکی میں ترقی کرے گا اسی قدر وہ اپنے پچھلے گناہوں کے بدنتائج سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا.وَ اصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ۰۰۱۱۶ اور( اس میں) صبر(و استقلال) سےکام لے.کیونکہ اللہ (تعالیٰ) نیکوکاروں کے اجر کو ہرگز ضائع نہیں (کیا)کرتا.تفسیر.کامیابی کے لئے استقلال بھی شرط ہے یعنی استقلال شرط ہے.جب اللہ تعالیٰ بداعمال کا نتیجہ نکالتا ہے تو نیکی کا نتیجہ کیوں نہ نکالے گا.مگر شرط یہ ہے کہ گھبرانا اور کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
Page 385
فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ پھر( تعجب ہے کہ) کیوں ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے (زمانہ میں) تھیں ایسے عقل مند (لوگ) نہ نکلے جو يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا (لوگوں کو) ملک میں بگاڑ پیدا کرنے سے روکتے سوائے چند ایک کے جنہیں ہم نے (ان کے بدیوں سے رکنے اور مِنْهُمْ١ۚ وَ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَاۤ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَ كَانُوْا روکنے کی وجہ سے) بچا لیا.اور( باقی لوگ) جنہوں نے ظلم( کا شیوہ اختیار) کیا تھا اس (مال و متاع) کے پیچھے پڑ مُجْرِمِيْنَ۰۰۱۱۷ گئے.جس میں (کہ) انہیں آسودگی بخشی گئی تھی اور مجرم ہو گئے.حلّ لُغات.بَقِیَّۃٌ.اَلْبَقِیَّۃُ مَثَلٌ فِی الْجَوْدَۃ وَالْفَضْلِ.کمال اور فضل بیان کرنے کے لئے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں.یُقَالُ فُلَانٌ بَقِیَّۃُ الْقَوْمِ اَیْ مِنْ خِیَارِھِمْ.بَقِیَّۃُ الْقَوْمِ کے معنے قوم کے بہترین افراد کے ہوتے ہیں.اُولُوْا بَقِیَّۃٍ اَیْ مِنَ الرَّأْیِ وَالْعَقْلِ اَوْ اُولُواا لْفَضْلِ.اُوْلُوا بَقِیَّۃٍ سے مراد اچھی رائے والے عقلمند اور فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں.(اقرب) اَ تْرَفَ أَتْرَفَتِ النِّعْمَۃُ زَیْدًا نَعَّمَتْہُ.نعمت نے زید کو آسودہ حال کر دیا.أَطْغَتْہُ وَأَبْطَرَتْہُ نعمت نے اسے سرکش اور متکبر بنا دیا.(اقرب) تفسیر.دوسرے لوگوں کی خبر اور فکر نہ رکھنا مستوجب عذاب بنا دیتا ہے یعنی جب ہمیشہ سے یہ قانون چلا آیا ہے کہ اگر لوگوں کی خبر نہ رکھی جائے تو لوگ بگڑتے چلے جاتے ہیں تو کیوں عقلمند لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانا اور اس بدی کے خمیر کو بڑھنے دیا جو آخر قوم کو تباہ کر دیتا ہے.اور کیوں نہ اس خمیر کو ہی ختم کر دیا.مگر افسوس کہ بہت کم لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور بجائے اس کے کہ عذاب کی حقیقت پر غور کرکے آئندہ سے اپنی قوم کو عذاب سے بچاتے پہلی تباہ شدہ قوموں کے اموال کے سمیٹنے میں لگ گئے اور خود بھی ظالم بن کر خدا تعالیٰ سے دور جاپڑے.
Page 386
وَ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ۰۰۱۱۸ اور تیرا رب ایساہرگز نہیں ہے کہ (ملک کی) آبادیوں کو باوجود اس کے کہ ان کے رہنے والے اصلاح (کے کام) کرنے والے ہوں ہلاک کر دے.حلّ لُغَات.اِصْلَاحٌ.اَصْلَحَ ضِدُّ اَفْسَدَ.فساد کے خلاف معنے دیتا ہے.اَصْلَحَ الْاَمْرَ.اَقَامَہٗ بَعْدَ فَسَادِہٖ کام کے خراب ہونے کے بعد اسے درست کر دیا.اَصْلَحَ بَیْنَ الْقَوْمِ.وَفَّقَ.آپس میں اتفاق کرادیا.اَصْلَحَ اِلَیْہ.اَحْسَنَ اِلَیْہِ.اس پر احسان کیا.(اقرب) تفسیر.بغیر جرم کے عذاب دینا ظلم ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ بغیر جرم کے عذاب دینا ظلم ہے.آج مسلمانوں پر عذاب پر عذاب نازل ہورہے ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستہ پر قائم ہیں.گویا وہ خدا کو ظالم مگر اپنے آپ کو نیک قرار دیتے ہیں.اس آیت سے دو سبق حاصل کئے جاسکتے ہیں.(۱) عذاب بغیر فساد کے نہیں آتا.پس جب عذاب کے آثار ظاہر ہوں تو ہوشیار ہو جانا چاہیے.عذاب کو دور کرنے کا گُر (۲)عذاب کو دور کرنے کا گر یہ ہے کہ قوم آپس میں صلح کرلے.اور نیکی کا وعظ کرنا شروع کر دے.یعنی آپس میں اتحاد ہو.اور دوسروں کی بدیاں دور کرنے کی کوشش کی جائے.یہ علاج ہی حقیقی علاج ہے.کیونکہ کسی قوم میں تنزل کے آثار پیدا ہوجانے کی دو ہی وجہیں ہوتی ہیں.(۱) قوم میں تفرقہ ہو.(۲) اس میں کمزوریاں پیدا ہوجائیں.جب تنزل کے اسباب کو دور کر دیا جائے گا تو لازماً ترقی ہوگی.وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا اور اگر تیرا رب اپنی (ہی) مشیت نافذ کرتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا تا اور( چونکہ اس نے ایسا نہیں کیا) يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَۙ۰۰۱۱۹اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ١ؕ وَ لِذٰلِكَ وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے.سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا ہے.اور اسی (رحم کا مورد بنا نے کے)
Page 387
خَلَقَهُمْ١ؕ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ لئے اس نےانہیں پیدا کیا ہے اور تیرے رب کا (یہ) فرمودہ یقیناً پورا ہو گا (کہ) میں جہنم کو یقیناًان سب جنوں اور الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۰۰۱۲۰ انسانوں سے (جو اختلاف کا موجب بنتے ہیں )پُر کروں گا.تفسیر.نیکی کا نشان صبر میں ترقی ہے اس آیت کو پچھلی آیات سے ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا نیکی میں ترقی کرتا جائے اتنا ہی صبر میں بڑھتا جاتا ہے.اور جس قدر صبر میں ترقی کرتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں.انسان کو رحم کے لئے پیدا کیا گیا ہے وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْسے مراد یہی ہے کہ انسان کو رحم کے لئے پیدا کیا ہے.نہ یہ کہ اختلاف کے لئے پیدا کیا ہے.کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہےوَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.(الذاریات :۵۷) اور اسی طرح فرماتا ہے رَحْمَتِيْ وَ سِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف :۱۵۷) وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَکے معنے وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ کا مطلب یہ ہے کہ متبعین شیطان سے جہنم کو بھر دوں گا.نہ یہ کہ سب انسانوں کو.کیونکہ اس جگہ ایک وعدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے.پس اس کے وہی معنے لئے جاسکتے ہیں جو اس وعدہ کے مطابق ہوں اور جب ہم اس وعدہ کی تلاش قرآن کریم میں کرتے ہیں تو کہیں بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ میں سب انسانوں کو جہنم میں ڈالوں گا.بلکہ اس کے برخلاف یہ وعدہ ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اس نے فرمایا کہلَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ.کہ تو بے شک انسانوں کو ورغلا مگر یہ یاد رکھ کہ میں انسانوں میں سے جو تیرے تابع ہوں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا.(الاعراف:۱۹) پس زیر تفسیر آیت میں سورہ اعراف کے وعدہ کا ہی ذکر ہے.کیونکہ اس کے سوا اس بارہ میں اور کوئی وعدہ قرآن کریم میں بیان نہیں ہے.اور اس کے معنے یہی ہیں کہ متبعین شیطان کے ذریعہ سے جہنم کو بھرا جائے گا.نہ یہ کہ مومنوں کو بھی بلاقصور و بے گنہ اللہ تعالیٰ جہنم میں دھکیل دے گا.اس وعدئہ الٰہی کے ذکر کی وجہ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اس وعدہ کا کیوں ذکر کیا ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو رحم ہی کے لئے پیدا کیا ہے.پس طبعاً اس بیان پر یہ الجھن پیدا
Page 388
ہوتی تھی کہ جب انسان کو رحم کے لئے پیدا کیا تھا تو پھر اسے سزا کیوں ملے گی؟ پس اس الجھن کو یوں دور کر دیا کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا تو رحم کے لئے ہی کیا تھا مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو لوگ شیطان کے پیرو ہوں گے ان کے حق میں رحم کا وعدہ فوراً پورا نہ ہوگا.بلکہ جو شیطان سے جو ناری وجود ہے تعلق پیدا کریں گے انہیں اس مناسبت کی وجہ سے پہلے آگ میں ڈالا جاوے گا تا انہیں معلوم ہو جائے کہ نوری وجود کو چھوڑ کر انسان اپنے مقام سے کس قدر گر جاتا ہے.دوزخیوں کے حق میں اس وعدہ کا پورا ہونا دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ میں فرمایا تھا ہم نے انسان کو رحمت کے لئے ہی پیدا کیا ہے.اس لئے اسے رحمت میں ہی داخل کریں گے.اس سے سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایک حصہ کے لئے تو آپ فرماچکے ہیں کہ میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا وہ وعدہ کہاں گیا.تو اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ وعدہ تو پورا ہو چکا ہے اب رحمت کا وعدہ پورا ہوگا.گویا یہ سوال اس وقت ہوگا کہ جب دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا.وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ اور ہم (اپنے) رسولوں کی خبروں میں سے اس سارے (کے سارےکلام) کو جس کے ذریعہ سے ہم تیرے دل کو فُؤَادَكَ١ۚ وَ جَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى ثبات بخشنے والے ہیں تیرے پاس بیان کرتے ہیں.اور ان (خبروں کے ضمن) میں تیرے پاس کامل حق اور لِلْمُؤْمِنِيْنَ۰۰۱۲۱ مومنوں کےلئے ایک (تسلی بخش) وعظ اور نصیحت آئی ہے.تفسیر.قرآن کریم میں انبیاء کی اخبار بطور قصہ نہیں اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے انبیاء کی اخبار بطور تاریخ بیان نہیں ہوئیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو ان میں بطور پیشگوئی بیان کیا گیا ہے.اگر ایسا نہ ہوتا تو ان واقعات کے بیان کرنے سے آپ کو تسلی کس طرح ہوسکتی تھی.ہاں اگر انہیں پیشگوئی کے طور پر سمجھا جائے تو ضرور آپؐ کے لئے وہ واقعات تسلی کا موجب بن جاتے ہیں.
Page 389
کیونکہ آپؐ کو اس طرح اپنی قوم کی شرارتوں اور ان کے برے انجام اور آپؐ کی فتوحات کا علم ہو گیا کیونکہ سب انبیاء کا بروز ہونے کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ان انبیاء کے حالات میں سے بھی آپؐ گزرتے.جَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ کے معنی اور یہ جو فرمایا ہے کہ اس میں تیرے لئے حق آیا ہے اس سے مراد یہ سورۃ ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ قصے بیان نہیں ہوئے بلکہ ایک پوری ہوکر رہنے والی بات بیان کی گئی ہے.نیز اس میں وعظ بھی ہے اور مومنوں کے فرائض بھی یاد دلائے گئے ہیں.وَ قُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ١ؕ اِنَّا اور جو( لوگ) ایمان نہیں لائے انہیں کہہ دے کہ تم اپنے درجہ کے مطابق کام کرتے جاؤہم (بھی جیسا کہ دیکھتے ہو عٰمِلُوْنَۙ۰۰۱۲۲ اپنے درجہ کے مطابق) کام کر رہے ہیں.تفسیر.اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْکے معنے یعنی جھگڑے فساد کی ضرورت نہیں ہے.جب ہمارے اعمال الگ الگ ہیں اور ہر اک ان کا ذمہ دار ہے تو نتائج خود بتادیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں.لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَ انْتَظِرُوْا١ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ۰۰۱۲۳ اور تم( بھی انجام کا)انتظار کرو.ہم (بھی) یقیناً انتظار کر رہے ہیں.تفسیر.کفار کا عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ غلط ہے یعنی گھبرانا تو ہم کو چاہیےنہ کہ تم کو کیونکہ تمہاری طرف سے دکھ ہم کو دیا جارہا ہے.مگر ہم صبر سے کام لے رہے ہیں.اور تم گھبرا رہے ہو.
Page 390
وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ (تعالیٰ) ہی کے قبضہ میں ہے.اور اسی کی طرف اس تمام معاملہ کو لوٹایا جائے گا فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ١ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا پس تو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ کر اور جو کچھ تم (لوگ) کرتے ہو تَعْمَلُوْنَؒ۰۰۱۲۴ اس سے تیرا رب ہرگز بے خبر نہیں.تفسیر.یہ پیشگوئیاں پوری ہوکر رہیں گی یعنی گو بظاہر وہ پیشگوئیاں جو اس سورۃ میں کی گئی ہیں بعید از قیاس معلوم ہوتی ہیں لیکن نتائج کا نکالنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے.پس گو یہ باتیں آج عجیب معلوم ہوتی ہیں لیکن وقت پر پوری ہوکر رہیں گی.غناء الٰہی سے مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے مومن کو بھی توجہ دلائی ہے کہ گو اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو چکا ہے پھر بھی وہ غنی ہے اور اس کی کمزوریوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ اپنے فیصلہ میں دیر کردے اس لئے اسے چاہیےکہ عبادت میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر پورا یقین رکھے تاکہ اس کا عمل خدا تعالیٰ کے فیصلہ کو نازل کرنے میں ممد ہو.
Page 391
سُوْرَۃُ یُوْسُفَ مَکِّیَّۃٌ سورہ یوسف.یہ سورۃ مکّی ہے.وَھِیَ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ مِائَۃٌ وَّ اثْنَتَا عَشْـرَۃَ اٰیَۃً وَ اثْنَا عَشَرَ رُکُوْعًا اور بسم اللہ سمیت اس کی ایک سو بارہ آیتیں ہیں اور بارہ رکوع ہیں.یہ سورۃ مکّی ہے اکثر صحابہ کے نزدیک سورہ یوسف ساری کی ساری مکی ہے لیکن ابن عباسؓ اور قتادہ کا قول ہے کہ پہلی تین آیات کے سوا باقی سب مکی ہے.سورہ یوسف ؑکا سورہ ہود سے تعلق اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ سلوک کے دو پہلو بیان فرمائے تھے.ایک سزا کا اور دوسرا رحم کا.سزاء کے پہلو کو سورہ ہود میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے.سزا کے پہلو کو پہلے بیان کرنے کی وجہ اور اس کو پہلے اس لئے بیان کیا ہے کہ جب کفار کی جزا کا وقت آیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے پہلے سزا کا معاملہ کیا گیا تھا اور سورہ یوسف میں رحم کا پہلو لیا گیا ہے کیونکہ نبی کریمؐ کے آخری ایام میں رحم سے کام لے کر آپؐ کے مخالفوں کو معاف کر دیا گیا تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں آپؐ کے مخالفوں سے بھی قیامت کا سا معاملہ کیا گیا.وہاں بھی پہلے مجرموں کو دوزخ میں ڈالا جاوے گا اور وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا.سورہ یوسف کی ایک خصوصیت کہ اس میں ایک ہی نبی کےحالات تفصیلاً پیش کئے گئے ہیں اس سورۃ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں ایک ہی واقعہ تفصیل و بسط سے بیان کیا گیا ہے اور کسی سورۃ میں ایسا نہیں کیا گیا.باقی سورتوں میں ایک مضمون بیان ہوتا ہے اور مختلف واقعات کے چھوٹے چھوٹے فقرے تشریح کے لئے لائے جاتے ہیں.آنحضرت کی اور حضرت یوسف کی زندگیوں کی تفصیلات میں مماثلت اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تفصیلات میں بھی ملتی ہے.پس حضرت یوسفؑ کی تفصیلی زندگی بیان کی ہے.تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ زندگی کے لئے بطور پیشگوئی ہو.سورہ یوسف میں تفصیلات کو بھی اور سورہ یونس میں صرف انجام کوذکر کرنے کی وجہ سورہ یونس
Page 392
میں رحم کی مثال کے لئے یونس علیہ السلام کا واقعہ لیا تھا اور یہاں تفصیل میں آکر یوسف علیہ السلام کو لیا ہے.اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ حضرت یونسؑ کے واقعہ میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں صرف انجام کی مشابہت ہے اور درمیانی تفصیلات کی مشابہت نہیں.لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں نہ صرف انجام کی مشابہت ہے بلکہ درمیانی واقعات میں بھی ہے.دوسری وجہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کے واقعہ میں صرف یہ مشابہت ہے کہ وہاں بھی قوم بچ گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی بچ گئی لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کو مزید مشابہت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو انہی کے ذریعہ سے نجات دی.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی بخشش کا اعلان بھی خود آپؐ ہی کے منہ سے کرایا.برخلاف حضرت یونسؑ کی قوم کے کہ ان کی نجات کا اعلان حضرت یونسؑ کے ذریعہ سے نہیں ہوا بلکہ خدا تعالیٰ کے فعل کے ذریعہ سے ہوا.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (میں) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں).الٓرٰ١۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ۫۰۰۲ الٓرٰ یہ (حقائق کو) روشن کرنے والی کتاب کی آیات ہیں.تفسیر.اس سورۃ میں بھی روئت کے مضامین پر بحث ہے الٓرٰ.میں اللہ ہوں جو دیکھتا ہوں.اس سورۃ میں بھی روئیت کے مضمون پر بحث کی گئی ہے اور بتایا ہے کہ اس رسولؐ کے حالات یوسفؑ کے حالات سے ملتے ہیں.پس اگر اس کے انجام کے ظہور سے پہلے اسے مفتری کہنا درست نہ تھا تو اسے مفتری کیونکر کہا جاسکتا ہے.یہ اشارئہ بعیدمخا طبین کے حال کی بناء پر ہے تِلْکَ کے لفظ سے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سورۃ میں جو پیشگوئی بیان ہوئی ہے وہ تم کو بعید نظر آتی ہے لیکن وہ ایک دن ضرور ہی پوری ہوکر رہے گی.لفظ مبین میں دلائل کی طرف اشارہ ہے مُبِیْنٌ کہہ کر بتایا ہے کہ یہ کتاب دلائل اور براہین ساتھ رکھتی ہے اور نہ صرف خود واضح ہے بلکہ اپنے سے پہلی کتب پر بھی روشنی ڈالتی ہے.
Page 393
مُبِیْن کے لفظ میں اعتراض اختلاف کا بھی جواب دیا گیا ہے اس لفظ سے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو قرآن کریم پر آئندہ ہونے والے تھے.یعنی اس میں پچھلی کتب کی بیان کردہ تاریخ سے اختلاف ہے اور بتایا ہے کہ قرآن کریم کا تو فرض ہے کہ پچھلی کتب کی غلطیوں کو بیان کرے پھر اختلاف کیوں نہ ہو.اس سورۃ میں لفظ مُبِیْنٌ رکھنے کی وجہ اس سورۃ میں مُبِیْنٌ کا لفظ اختیار کیا گیا ہے اور سورۃ ہود میں فُصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ کہا گیا تھا.اس کی یہ وجہ ہے کہ سورہ ہود میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایسے مضامین کے بیان کئے گئے تھے جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوتی تھی اور یہاں ایک ہی لمبا مضمون چلا جاتا ہے.پس چونکہ فَصَّلَ کے معنے الگ الگ کرنے کے ہیں وہاں فُصِّلَتْ کا لفظ رکھا گیا اور یہاں مُبِیْنٌ کا لفظ رکھا گیا.جس کے معنے وضاحت کے ہیں.اس لفظ میں قرآن کریم کے ذاتی کمال کی طرف بھی اشارہ ہے مُبِیْنٌ کے لفظ سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اپنی ذات میں کامل کتاب ہے اور اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے بیرونی دلیل کی محتاج نہیں بلکہ خود ہی دعویٰ بیان کرتی ہے اور خود ہی دلیل بھی دیتی ہے.اس لفظ میں قرآن کریم کی جامعیت کی طرف بھی اشارہ ہے مُبِیْنٌ کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وصول الی اللہ کے لئے جس قدر امور کی ضرورت ہے ان کو یہ کتاب واضح کردیتی ہے.اسی طرح تمام وہ امور جو احکام یا اخلاق فاضلہ یا اعتقادات صحیحہ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ان سب کو بیان کرتی ہے.اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۰۰۳ اس (اپنے مطالب کو) خوب واضح کرنے والے قرآن کو یقیناًہم نے اتارا ہے تاکہ تم( اس میں) عقل (اور تدبر) سے کام لو.حلّ لُغَات.عَرَبیٌّ عَرَبیٌّ کا لفظ عَرَبٌ کی طرف منسوب ہے.اور عَرَبٌ عَرِبَ یَعْرَبُ کی مصدر بھی ہے اور صفت مشبہ بھی.اور نیز یہ عَرُبَ کی مصدر ہے اور یہ ملک عرب کا نام بھی ہے اور اس ملک کی اصلی اور پرانی باشندہ قوم کا نام بھی.عَرِبَ کے معانی حسب ذیل ہیں.جن میں سے ہر ایک میں پری اور بھرا ہوا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے.عَرِبَت الْمِعْدَۃُ عَرَبًا تَغَیَّرَتْ وَفَسَدَتْ.زیادہ کھانے سے فساد معدہ ہو گیا.عَرِبَ الْجُرْحُ نُکِسَ وَغَفَرَ وَبَقِیَ
Page 394
اَثَرُہٗ بَعْدَ الْبَرْءِ.زخم اوپر سے اچھا ہوکر اندر سے ازسرنو بھر گیا.اور اس کا منہ بند رہا.تَوَرَّمَ وَتَقَیَّحَ.زخم پھول گیا.اور اس میں پیپ پڑ گئی.فُلَانٌ فَسَدَتْ مِعْدَتُہٗ.اسے بدہضمی ہو گئی.نَشِطَ.اس کے جسم میں چستی پیدا ہو گئی.اور امنگ سے بھر گیا.فَصُحَ بَعْدَ لُکْنَۃٍ.بغیر کسی رکاوٹ کے خوب بولنے لگ گیا اور اس کی صفت مشبہ بھی عَرَبٌ ہی آتی ہے.النَّہْرُ غَمَرَ.اور جب یہ لفظ نہریا دریا کے لئے بولا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں بھر گیا.اور اس کا پانی بہت اونچا ہو گیا.(اقرب) پس عَرَبٌ مصدر کے ان تمام معانی کا قدر مشترک بھرا ہوا ہونا.یا بھر جانا ہوا.جس کے ساتھ یاء نسبت کے لگنے سے اس کے معنے ہوئے خوب بھری ہوئی چیز.کیونکہ یاء نسبت کے لگانے سے وصفی معنے کے علاوہ مبالغہ کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے اور عَرَبٌ صفت مشبہ کے معنے بھری ہوئی چیز کے ہوئے.اور جب اس کے ساتھ یاء نسبت لگائی جائے تو جس طرح اَحْمَرُ کے مقابلہ میں اَحْمَرِیُّکے معنے بہت سرخ کے اور عَبْقَرٌ کے مقابلہ میں عَبْقَرِیٌّ کے معنی نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی چیز کے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے معنے ہوں گے.خوب بھری ہوئی چیز اور جب یہ لفظ کسی کتاب کی صفت واقع ہو تو ان معنوں کی رو سے کتابٌ عَرَبیٌّ کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ نہایت پرمعانی کتاب ہے.کیونکہ جس چیز سے کسی کتاب کو بھری ہوئی کہا جاسکتا ہے وہ اس کے معانی اور مطالب ہی ہوسکتے ہیں.اور جب ایک زبان کو اس صفت سے موصوف کریں گے تو اس کا یہ مدعا ہوگا کہ اس کے مفردات نہایت ہی کثیرالمعانی اور وسیع مفہوم رکھنے والے ہیں.اور عَرُبَ عَرَبًا کے معنے ہیں کَانَ عَرَبیًّا خَالِصًا وَلَمْ یَلْحَنْ تَکَلَّمَ بِالْعَرَبِیَّۃِ وَکَانَ عَرَبِیًّا فَصِیْحًا.زبان کا ہر ایک نقص سے پاک اور خالص عربی اور خوب واضح ہونا.فصیح عربی بولنا اور اپنے مدعا کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرنا.(اقرب) اور یائے نسبت کے لگانے سے اس کے معنے نہایت فصیح اور خوب واضح ہر ایک نقص سے بالکل پاک کے ہوجائیں گے.اور ان معنوں کی مزید وضاحت اس لفظ کی مختلف تصریفات سے بھی ہوتی ہے.چنانچہ اقرب الموارد میں ہے اَعْرَبَ الشَّیْءَ اَبَانَہٗ وَاَوْضَحَہٗ خوب بیّن اور واضح کر دیا.عَنْ حَاجَتِہٖ اَبَانَ عَنْھا کھول کر بیان کیا.کَلَامَہٗ حَسَّنَہٗ وَاَفْصَح وَلَمْ یَلْحَنْ فِی الْاِعْرَابِ.بات میں حسن پیدا کیا.اور اسے خوب واضح کیا.اور تلفظ میں بھی کوئی غلطی نہ کی.بِحُجَّتِہٖ اَفْصَحَ بِہَا.اپنی بات خوب کھول کر مدلل طور پر بیان کی.اور مفردات راغب میں ہے اَلْعَرَبِیُّ اَلْمُفْصِحُ.عربی کے معنی ہیں اپنے مدعا کو خوب صفائی اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا.
Page 395
وَالْاِعْرَابُ اَلْبَیَانُ.اور اعراب کے معنے کھولنے اور واضح کرنے کے ہیں.پس ان معنوں کی رو سے قُرْاٰنٌ عَرَبِیٌّ کے معنی ہوئے ایسی کتاب جو ہمیشہ پڑھی جانے والی اور اپنے مطالب کو نہایت وضاحت کے ساتھ اور مدلل طور پر بیان کرنے والی ہے.تفسیر.قرآن کریم بکثرت لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا ان آیات میں نہایت لطیف طور پر دو دعوے قرآن شریف کے متعلق بیان کئے ہیں.(۱) پہلی آیت میں قرآن کریم کا نام الکتاب رکھ کر بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ لکھا جایا کرے گا اور کتابی صورت میں ہی رہے گا.اور دوسری آیت میں قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا کہہ کر یہ بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھا جائے گا کیونکہ بعض کتب ایسی ہیں جو لکھی تو بہت جاتی ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتیں جیسے انجیل کہ چھپتی بہت ہے لیکن پڑھی کم جاتی ہے.اور بعض کتابیں لکھی کم جاتی ہیں لیکن پڑھی زیادہ جاتی ہیں جیسے گرنتھ وغیرہ.لیکن کسی کتاب کے پورے طور پر محفوظ رہنے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ بکثرت لکھی بھی جائے اور پڑھی بھی جائے اور یہ خصوصیت صرف قرآن کریم کو حاصل ہے.عربی زبان کی بعض خصوصیات عَرَبِیًّا.یوں تو اس کے معنے عربی زبان کے ہی ہیں لیکن عربی کا لفظ عرب سے نکلا ہے جس کے معنے بھرنے اور کثرت کے ہوتے ہیں اور جیسا کہ حل لغات میں بتایا جاچکا ہے.ع ر ب سے مشتق الفاظ جتنے بھی ہیں ان سب میں بھرنے اور کثرت کے معنے پائے جاتے ہیں.پس عربی زبان کو اسی وجہ سے عربی کہتے ہیں کہ اس کے معنوں میں بہت وسعت ہے اور اس کے مادے بہت زیادہ ہیں.ہر مضمون جو بیان کرنا چاہو اس کے لئے اس میں سامان موجود ہے.چنانچہ یورپین لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ زبان مادوں کے لحاظ سے بہت مکمل اور وسیع ہے.مثلاً لین پول مشہور مصنف جس نے تاج العروس کا ترجمہ کیا ہے اس کتاب میں حسرت سے لکھتا ہے کہ عربی جیسی زبان ہمیں کوئی نظر نہیں آتی.لاکھوں مادے عربی زبان میں پائے جاتے ہیں اور ہر مادہ بامعنی ہے جس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے.چنانچہ ابن جنی نے جو ایک بہت بڑا ادیب ہے اپنے استاد بوعلی کا یہ دعویٰ بیان کیا ہے کہ عربی زبان کے حروف میں ہی معنوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور مثال کے طور پر اس نے ک.ل.م.کو پیش کیا ہے کہ جب یہ حروف آپس میں مل کر استعمال ہوں تو قوت و طاقت کے معنے ضرور ان میں ملحوظ ہوتے ہیں.مثلاً مَلِکٌ بادشاہ.مَلَکٌ فرشتہ.کَلْمٌ زخم لَکْمٌ تھپڑ وغیرہ.ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ گو حروف آگے پیچھے ہو گئے ہیں اور معنے بدلتے چلے گئے ہیں لیکن سب کے سب الفاظ میں قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے.اسی طرح عربٌ کا لفظ ہے اس کے بھی جس قدر مشتقات ہیں سب میں بھرنے اور بہت ہوجانے کے
Page 396
معنے پائے جاتے ہیں جیسے عبور ، رعب وغیرہ.عربی زبان کے اُمّ الاَلْسِنہ ہونے کا کمال حضرت مسیح موعود ؑ نے ہی ثابت کیاہے عربی زبان کے ان کمالات کی طرف گو پہلے آئمہ زبان نے بھی توجہ دلائی ہے لیکن یہ حقیقت کہ یہ زبان اُمّ اَلاَلْسِنہ ہے یعنی سب زبانیں اسی میں سے نکلی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ نے ہی ظاہر کی ہے اورا س مضمون پر ایسے لطیف پیرایہ میں روشنی ڈالی ہے کہ کوئی اس حقیقت کا انکار نہیں کرسکتا.افسوس کہ آپؑ کی کتاب نامکمل رہ گئی ہے مگر اصول بیان ہوچکے ہیں.ایک صاحب نے اس کی نقل میں ایک کتاب لکھی ہے لیکن افسوس کہ حقیقت کو بوجہ لاعلمی ملیامیٹ کر دیا ہے.عربی زبان سے تدبر کا خاص تعلق لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.یعنی اس زبان میں اس کلام کو اس لئے اتارا ہے کہ تا تم پورا فائدہ اٹھا سکو.اگر یہ قرآن عربی نہ ہوتا یعنی ایسی زبان میں نہ آتا جو ہر مفہوم کو ادا کرسکتی ہے تو لوگ پورا فائدہ نہ اٹھاسکتے.نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ ہم تیرے پاس (ہر امر کو) بہترین طور پر بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس قرآن کو تیری طرف (حقائق پر مشتمل) اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ١ۖۗ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ۰۰۴ وحی (کےذریعہ سے نازل) کیا ہے.اور اس سے پہلے یقیناً تو (ان حقائق سے) بے خبر وں میں سے تھا.حل لغات.قَصَّ قَصَّ یَقُصُّ قَصًّا وقَصَصًا اٰثَرَہُ تَتَبَّعَہٗ شَیْئًا بَعْدَ شیْءٍ.اس کا نشان تلاش کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا.وَمِنْہُ فَارْتَدَّا عَلٰی اٰثَارِھِمَا قَصَصًا.اَیْ رَجَعَا فِی الطَّرِیْقِ الَّتِیْ سَلَکَا ھَا یَقُصَّانِ الْأَثَرَ.اور انہی معنوں میں قرآن کریم کی آیت فَارْتَدَّاعَلٰی اٰثَارِھِمَا قَصَصًا.میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.قَصَّ عَلَیْہ الْخَبْرَ وَالرُّؤْیَا حَدَّثَ بِھِمَا عَلٰی وَجْھِھِمَا بات کو بے کم و کاست بیان کیا.ٹھیک طور پر بیان کیا.وَمِنْہُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ.اَیْ نُبَیِّنُ لَکَ اَحْسَنَ الْبَیَانِ.اور انہی معنوں میں سورہ یوسف کی آیت نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ میں یہ لفظ آیا ہے.یعنی ہم تیرے سامنے ٹھیک ٹھیک بات بیان کرتے ہیں.(اقرب)
Page 397
تفسیر.یوسف ؑکے واقعہ کے متعلق دنیا میں اختلاف تھا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسفؑ کے واقعہ کے متعلق دنیا میں اختلاف تھا اور قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا اور جو اصل واقعہ ہے اس کے چہرہ پر سے باطل کا نقاب اٹھاو ے گا.تبھی تو فرماتا ہے کہ ہم بے کم و کاست اصل واقعہ بیان کریں گے.اگر دنیا میں یہ واقعہ مشتبہ نہ ہوتا تو ان الفاظ کے استعمال کی ضرورت ہی کیا تھی.مگر تعجب ہے یوروپین محققین پر جنہوں نے اس امر پر غور نہیں کیا کہ حضرت یوسفؑ کا واقعہ قرآن کریم سے پہلے ہی مختلف فیہ ہوچکا تھا اور تاریخی طور پر مجروح ہو گیا تھا اور صرف اس امر کو دیکھ کر کہ قرآن کریم میں یہ واقعہ بائبل سے مختلف طور پر بیان ہوا ہے اس پر حملہ کر دیا ہے.واقعہ یوسف کے پیش نظر برنکمین کا قرآن کریم پر حملہ اور اس کا جواب چنانچہ ایک مشہور جرمن برنکمین نے نوٹس آن اسلام صفحہ ۱۱۲ پر لکھا ہے کہ ایک مسلمان پر قرآن کو بائبل سے ادنیٰ ثابت کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اس کے سامنے دونوں کتابوں میں سے یوسف کے واقعہ کو پیش کر دیا جائے.قرآن شریف نے ایک خوبصورت اور دردانگیز واقعہ کو نہایت خراب اور بدنما صورت میں پیش کیا ہے.اس اعتراض نے درحقیقت قرآن کریم کی سچائی کوثابت کر دیا ہے.کیونکہ اس کا یہ دعویٰ کہ ہم بلاکم و کاست بیان کریں گے ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا جانتا تھا کہ لوگ اس کے بیان کردہ واقعات پر اعتراض کریں گے.باقی رہا برنکمین صاحب کا یہ اعتراض کہ قرآن کریم نے ایک خوبصورت واقعہ کو خراب شکل میں پیش کیا ہے سو اس کا جواب اگلی آیتوں میں آجائے گا اور پڑھنے والوں کو خود معلوم ہو جائے گا کہ کس نے واقعہ کو بدنما صورت میں پیش کیا ہے.بِمَاۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَیْکَ کے معنی اور یہ جو فرمایا کہ اس واقعہ کے بے کم و کاست بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تیری طرف قرآن کریم نازل کیا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والا تھا.کیونکہ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے قصہ کے بیان کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے.ہاں اس امر کا ضرور تعلق ہے کہ ان پیشگوئیوں کو بیان کیا جائے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن کریم کی وحی پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین حاصل ہو.دوسرے یہ معنے ہوسکتے ہیں کہ حامل قرآن نے چونکہ مثیل یوسف ہونا تھا اس وجہ سے ضروری تھا کہ اسے اس کے حالات زندگی بتائے جائیں.مِنَ الْغٰفِلِيْنَ میں کس بات سے بے خبری کی طرف اشارہ ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ تو اس سے پہلے
Page 398
بے خبر تھا اس کے دو معنے ہوسکتے ہیں.اول یہ کہ تو اس واقعہ سے غافل تھا.کیونکہ نہ تو تورات میں ہی ایک جگہ تمام صداقتیں جمع کی گئی ہیں اور نہ طالمود میں ہی، کوئی سچائی کسی جگہ ہے اور کوئی کسی جگہ.عیسائی کہتے ہیں کہ جبکہ یہ واقعہ بائبل میں موجود تھا تو آپؐ بے خبر کس طرح ہوسکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو واقعہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے وہ اور ہے اور قرآن کریم کا بیان کردہ اور ہے.اور جیسا کہ میں آئندہ ثابت کروں گا قرآن کریم کا بیان ہی درست ہے اور جہاں جہاں اس سے بائبل نے اختلاف کیا ہے اس میں بائبل نے ٹھوکر کھائی ہے.دوسرے یہ معنے ہیں کہ تجھے بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ تیرے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آنے والے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آنے والے ہیں.اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ (تو یاد کر اس وقت کو) جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا (تھا) کہ اے میرے باپ( یقین مانیے) میں نے گیارہ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ۰۰۵ ستاروں کواور سورج اور چاند کو( بھی رؤیا میں )دیکھا ہے (اور پھر مزید تعجب اس پر ہے کہ) میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے.حلّ لُغَات.اَبَتِ اَبَتِ اصل میں اُبِیْ ہے یعنی ’’میرے باپ‘‘! لیکن عربی زبان کے قاعدہ کے مطابق کہ اَبِیْ اور اُمِّیْ کی یاء متکلم کو نداء کے وقت تاء مکسورہ سے بدل دیتے ہیں اور یَااَبَتِ اور یَااَمَتِ کہہ دیتے ہیں اور اس سے ایک رنگ بے تکلفی اور محبت کا پیدا کردیتے ہیں اس جگہ یَااَبَتِ استعمال ہوا ہے.تفسیر.قرآن کریم کے اور بائبل کے بیان میں پہلا فرق طریق ابتداء کا ہے چونکہ بعض مسیحی مصنفوں نے قرآن پر حملہ کیا ہے اس لئے میں ساتھ ساتھ ہی وہ فرق بتلاتا جاؤں گا جو بائبل اور قرآن کریم کے بیان میں ہے.پہلا فرق تو یہ ہے کہ بائبل میں اس واقعہ کے بیان کو حضرت یوسفؑ کے نسب نامہ سے شروع کیا گیا ہے لیکن قرآن کریم نے اس کو یوسفؑ کی اس خواب سے شروع کیا ہے جو کہ یوسفؑ کی ساری زندگی کے واقعات کے لئے نقطۂ مرکزیہ کے طور پر ہے اور آپ کی زندگی کے سب نشیب و فراز اسی پر مبنی ہیں.اور نسب نامہ وغیرہ کو جو مؤرخین کا کام ہے چھوڑ دیا گیا ہے.پس اگر اور فرقوں کو چھوڑ کر محض شروع ہی کے لحاظ سے دونوں کے بیانوں میں
Page 399
فیصلہ کیا جائے اور کسی مبصر کے سامنے دونوں بیانوں کو رکھ کر اس سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم اور بائبل میں سے کس کا شروع اچھا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ قرآن کریم نے عمدہ طور پر اس واقعہ کو شروع کیا ہے.وہ چیز جس نے یوسفؑ کو کامیاب بنایا.اس کی زندگی میں تغیر پیدا کیا.اس کے بھائیوں کو دشمن بنا دیا.اور پھر آخر غلام بناکر اس کے قدموں میں لا ڈالا.یہی خواب تھی.پس اگر یوسفؑ کا اس زندگی کو جس سے دنیا سبق حاصل کرسکتی ہے پیش کرنا مقصود ہو تو اس خواب سے بہتر ابتداء اس کے لئے نہیں مل سکتی.دوسرا فرق.قرآن کریم نے ستاروں کا ذکر پہلے اور سورج چاندکا بعد میں کیا ہے دوسرا فرق بائبل کے بیان اور قرآن کریم کے بیان میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں گیارہ ستاروں کا پہلے ذکر ہے اور سورج اور چاند کا بعد میں لیکن بائبل میں اس کے برخلاف ہے.چنانچہ اس میں لکھا ہے.’’پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اسے اپنے بھائیوں سے بیان کیا.ا ور کہا کہ دیکھو میں نے ایک خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستاروں نے مجھے سجدہ کیا اور اس نے یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بیان کیا.‘‘ (پیدائش باب۳۷ آیت ۹،۱۰) اس اختلاف سے قرآن کریم کی برتری اور بائبل کی کمزوری نہایت واضح ہوجاتی ہے.قرآن کریم اور بائبل دونوں متفق ہیں کہ ستاروں سے مراد بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں.لیکن جیسا کہ بائبل خود تسلیم کرتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزت پا جانے کے بعد پہلے ان کے بھائی ان سے ملے ہیں اور ادب سے ان کے سامنے جھکے ہیں اور اس کے بعد ان کے باپ اور ماں ان کے پاس آئے ہیں.پس وہ ترتیب جو قرآن کریم نے رؤیا کی بیان کی ہے درست ہے اور بائبل کی بیان کردہ ترتیب خود اس کے اپنے بیان کے مطابق غلط ہے.یقیناً رؤیا میں انہی وجودوں کو پہلے دکھایا گیا ہوگا جنہوں نے پہلے یوسفؑ کے سامنے سر جھکانا تھا اور انہیں پیچھے دکھایا گیا ہوگا جنہوں نے بعد میں زیر سایہ آنا تھا.لفظ سجدہ سے مراد اس آیت میں جو سجدہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ واقعہ میں وہ سجدہ کریں گے بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ وہ ان کے تابع ہوجائیں گےا ور ایسا ہی ہوا کیونکہ حضرت یوسفؑ کے بھائی اور ماں باپ مصر میں آکر بس گئے جہاں وہ وزارت کے مرتبہ پر فائز تھے اور اس طرح وہ لوگ ان کے تابع فرمان ہو گئے.سورج چاند اور ستاروں سے مراد بادشاہ اور اراکین سلطنت نہیں ہوسکتے روح المعانی میں لکھا ہے کہ ماں باپ اور بھائیوں کی اطاعت چونکہ معمولی بات ہے پس یہاں سورج اور چاند سے کچھ اور مراد لینا چاہیے.
Page 400
مصنف کتاب کی رائے ہے کہ سورج سے مراد درحقیقت بادشاہ اور چاند سے مراد وزیر اور گیارہ ستاروں سے مراد اراکین دولت اور رؤسائِ دیار ہیں.لیکن یہ معنے درست نہیں کیونکہ بادشاہ یوسفؑ کے ماتحت نہیں ہوا.بلکہ وہ بادشاہ کے ماتحت تھے اور اس کے قوانین پر چلتے تھے.چنانچہ اس پر قرآن کریم شاہد ہے.فرماتا ہے مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ (یوسف :۷۷) یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو شاہی قانون کے مطابق نہیں روک سکتے تھے.(۲) بادشاہ کسی وزیر کا خواہ کتنا ہی احترام کرے اسے سجدہ کے لفظ سے موسوم نہیں کرسکتے کیونکہ وہ احترام اطاعت کا نہیں ہوتا بلکہ شفقت کا ہوتا ہے.اور سجدہ چونکہ کمال اطاعت کی ظاہری تمثیل کا نام ہے اس لئے اظہار اطاعت کی شکلوں پر ہی مجازاً بھی اس کا اطلاق کیا جاسکتا ہے.بادشاہ و وزراء ہی کی نہیں بلکہ والدین اور بھائیوں کی اطاعت بھی بڑی چیز ہے اصل بات یہ ہے ماں باپ اور بھائی کی اطاعت بھی بڑی بات ہے کیونکہ عام طور پر ماں باپ اپنی اولاد کے ماتحت نہیں ہوتے.خواب کا پورا ہونا بھی عظمت کا موجب ہے پھر یہاں تو معاملہ ہی اور ہے.حضرت یوسفؑ نے بچپن کی عمر میں خواب دیکھا ہے جس پر بتایا گیا ہے کہ ایک دن ان کے بھائی اور ماں باپ ان کی اطاعت میں آجائیں گے.کون شخص اس قدر عرصہ پہلے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور ترقی کرے گا اس کے گیارہ بھائی اور ماں باپ بھی زندہ رہیں گے اور ایک دن اس کے حکم کے نیچے آجائیں گے.حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھی ہے ان کی عمر صرف گیارہ بارہ سال کی تھی اور ان کے والد کی عمر پچاس سے اوپر تھی.پس ایسے وقت کی خواب کا پورا ہونا معمولی ہرگز نہیں کہلاسکتا.یوسف کے بھائیوں کے نام گیارہ ستاروں کی تعبیر میںمَیں نے بتایا ہے کہ گیارہ بھائی ہیں.ان کے نام بائبل سے یہ معلوم ہوتے ہیں.(۱) روبن (۲) سمعون (۳)لاوی (۴)یہودا (۵)دان (۶)نفقانی (۷)جد (۸) آشر (۹)اشکار (۱۰)زبلون (۱۱)بنیامین.(پیدائش باب ۲۹ ،۳۰ و ۳۵) ان سب کے معنے بھی بائبل نے بتائے ہیں اور سب کے سب عجیب و غریب ہیں.سوائے بن یامین کے سب نام ماؤں نے رکھے ہیں.رسول کریمؐ کی مماثلت حضرت یوسفؑ سے سب سے پہلی وحی الٰہی میں اس واقعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام سے دو مشابہتیں ہیں.اوّل آپؐ پر بھی غارحراء میں جو سب سے پہلی وحی آئی اس میں آپؐ کی سب قوم پر فضیلت پاجانے کی خبر تھی کیونکہ اس میں فرمایا گیا تھا کہ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ.الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ(العلق:۴ تا ۶).یعنی سب سے مکرم رب کی مدد سے
Page 401
یہ کلام تو لوگوں کو سنا.یعنی وہ تجھے بھی سب سے مکرم بنا دے گا اور تیری معرفت لوگوں کو وہ بات سکھائے گا جو پہلے لوگوں کو نہیں سکھائی تھی.یعنی تو موجودہ زمانہ کے لوگوں سے بھی مکرم ہوگا اور پہلے لوگوں سے بھی.کیونکہ تجھے وہ کچھ ملے گا جو پہلے انبیاء کو بھی نہیں ملا.گویا تو بھائیوں کا بھی سردار ہوگا اور اپنے روحانی آباء کا بھی یعنی انبیاء کا بھی.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَنَاسَیِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ(ابن ماجہ کتاب الزھد باب ذکر شفاعۃ).جس قدر انسان ہیں جن میں پہلے انبیاء بھی شامل ہیں میں ان سب کا سردار ہوں.اور سردار کی اطاعت کی جاتی ہے.اسی طرح فرمایا لَوْکَانَ مُوْسٰی وَعِیْسٰی حَیَّیْنِ لَمَا وَسِعَہُمَا اِلَّااتّباعیْ.اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا.(تفسیر ابن کثیر سورۃ آل عمران :۸۱ واذ اخذ اللہ میثاق..) غرض سب سے پہلی وحی ہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آپؐ کے بھائی اور آپ کے بزرگ خواہ وہ کتنے پرانے ہوں سب آپؐ کے ماتحت ہوں گے اور آپ سب کے سردار ہوں گے.دوسری مماثلت.سب سے پہلی وحی اپنے قومی بزرگ ورقہ بن نوفل کو سنانا دوسری مشابہت یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنی رؤیا اپنے باپ کو سنائی تھی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی وحی حضرت خدیجہؓ کے کہنے پر اپنے خاندان کے ایک بزرگ کو سنائی جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا(بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی علٰی رسول اللہ ).قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے اپنی (یہ) رؤیا اپنے بھائیوں کے پاس نہ بیان کیجیؤ ورنہ وہ تیرے متعلق لَكَ كَيْدًا١ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۰۰۶ (ضرور) کوئی( مخالفانہ) تدبیر کریں گے شیطان انسان کا یقیناً (کھلم) کھلا دشمن ہے.حلّ لُغات.بُنَیَّ بُنَیَّ اِبْنِیْ کی تصغیر ہے جو یاء ضمیر متکلّم کی طرف مضاف ہے.اور تصغیر کے صیغہ سے مراد چھوٹی عمر کا بچہ نہیں بلکہ پیار کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے.باپ بڑی عمر کے لڑکے کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کرسکتا ہے.کیونکہ باپ کے لئے بیٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے اور اس کے پیار کا مستحق.قرآن کریم میں بڑی عمر کے بیٹوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے.چنانچہ سورہ ہود میں ہی حضرت نوح ؑ کا قول گزر چکا ہے کہ انہوں نے
Page 402
طوفان کے وقت اپنے بیٹے سے کہا يٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا.( ہود:۴۳) اسی طرح سورۃ لقمان میں لقمان کا قول ہے يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ(لقمان:۱۴) کَادَ کَادَہٗ یَکِیْدُہٗ کَیْدًا خَدَعَہُ وَمَکَرَبِہٖ اسے دھوکہ دیا اور حیلہ بازی کی.وَالْاِسْمُ اَلْمَکِیْدَۃُ اور اس کا اسم مصدر مَکِیْدَۃ ہے جس کے معنی دھوکہ اور چالاکی کے ہیں.وَعَلَّمَہُ الْکَیْدَ.اور کَادَ کے ایک معنی ہیں اسے تدبیر سکھلائی.وَبِہٖ فُسِّرَ کَذٰلِکَ کِدْنَا لِیُوْسُفَ أَیْ عَلَّمْنٰہُ الْکَیْدَ عَلٰی اِخْوَتِہٖ.اور قرآن کریم میں یوسفؑ کے متعلق جو یہ لفظ آیا ہے اس کے بھی یہی معنے کئے گئے ہیں کہ ہم نے اسے تدبیر سکھائی.کَادَلَہُ.اِحْتَالَ لَہُ اس سے حیلہ بازی کی.فُلَانًا حَارَبَہٗ.اس سے جنگ کی.اَرَادَہٗ بِسُوْءٍ.اس سے بدی کا ارادہ کیا.اَلْکَیْدُ.الْمَکْرُوَالْخُبْثُ.کَید کے معنے مکر اور خباثت یعنی بدباطنی کے ہیں.اَلْحِیْلَۃُ تدبیر.اَلْحَرْبُ جنگ.اَرَادَۃُ مَضَرَّۃِ الْغَیْرِخُفْیَۃً دوسرے کو پوشیدہ طور پر تکلیف پہنچانے کا ارادہ.وَھُوَ مِنَ الْخَلْقِ الْحِیْلَۃُ السَّیِّئَۃُ وَمِنَ اللہِ التَّدْبِیْرُ بِالْحَقِّ لِمَجَازَاۃِ اَعْمَالِ الْخَلْقِ.اور جب یہ کسی مخلوق کا فعل ہو تو اس کے معنے بری تدبیر کے ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنے پکی اور مناسب تدبیر کے ہوتے ہیں جو انسانوں کے اعمال کا بدلہ دینے کے لئے اختیار کی گئی ہو.(اقرب) تفسیر.بائبل اور قرآن کریم کے بیان میں تیسرا فرق.یوسف نے صرف باپ کو اپنا خواب سنایا تھا بائبل اور قرآن کریم کے بیانات میں اس جگہ پھر اختلاف ہو گیا ہے اور پہلے کی طرح بائبل خود شاہد ہے کہ اس کا بیان غلط ہے.قرآن کریم نے تو بتایا ہے کہ یوسفؑ نے اپنا یہ خواب پہلے اپنے والد کو سنایا اور اس نے انہیں منع کر دیا کہ بھائیوں کو یہ خواب نہ سنائیو.لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے بھائیوں کو یہ خواب سنایا.(پیدائش باب۳۷ آیت ۹) اس اختلاف میں بھی قرآن کریم ہی صادق ہے.کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس خواب کے دیکھنے سے پہلے یوسفؑ نے ایک اور خواب دیکھا تھا.اور اپنے بھائیوں کو سنایا تھا.چنانچہ لکھا ہے.’’اور یوسف نے ایک خواب دیکھا اور اسے اپنے بھائیوں سے کہا تب وے اس سے زیادہ متنفر ہوئے.(پیدائش باب۳۷ آیت۵) پھر لکھا ہے.’’تب اس کے بھائیوں نے اسے کہا کہ کیا تو سچ ہمارا بادشاہ ہوگا یا تو ہمارا حاکم ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اور اس کی باتوں سے اس کا زیادہ کینہ پیدا کیا.(پیدائش باب۳۷آیت ۸) ان دونوں خوابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب سے پہلے بھی ایک خواب دیکھی تھی اور جب انہوں نے وہ خواب اپنے بھائیوں کو سنائی تو
Page 403
انہوں نے اسے ڈانٹا اور اس سے نفرت کرنے لگے اور کینہ کرنے لگے.اب کیا عقل تسلیم کرسکتی ہے کہ دوسری دفعہ جب انہوں نے ویسی ہی خواب دیکھی تو باپ کو سنانے سے پہلے اپنے بھائیوں سے کہی ہوگی.عقل یہی کہتی ہے کہ اس دفعہ پہلے سلوک سے ڈر کر انہوں نے بھائیوں سے خواب نہیں کہی ہوگی بلکہ والد سے کہی ہوگی.پس قرآن کریم کا بیان خود بائبل کے دوسرے حوالہ جات کو مدنظر رکھتے ہوئے زیادہ معقول اور قابل قبول ہے.بھائیوں کو خواب سنانے سے روکنے کی وجہ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کو خواب سنانے سے منع کیا اس کی وجہ قرآن کریم نے خود ہی بتادی ہے اور وہ یہ کہ انہیں رشک پیدا ہوگا کہ یہ لڑکا بڑا ہونے والا ہے اور غصہ میں وہ یہ نہ سوچیں گے کہ خواب دیکھنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ محض اس وجہ سے کہ اس کے بڑا ہونے کی بشارت اسے ملی ہے اسے اپنے راستہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے.چنانچہ بائبل بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ یوسفؑ کے بھائی اس وجہ سے اس سے ناراض تھے کہ یہ خوابیں دیکھتا ہے.آنحضرتؐ اور حضرت یوسفؑ کی تیسری مماثلت اس آیت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسفؑ کی ایک مشابہت بیان کی گئی ہے.کیونکہ جس طرح حضرت یوسفؑ کو خواب سنانے پر حضرت یعقوبؑ نے بتایا کہ اس رؤیا کو جب تیرے بھائی سنیں گے تو تیری مخالفت کریں گے.اسی طرح جب ورقہ بن نوفل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنائی تو انہوں نے کہا کہ یَالَیْتَنِیْ فِیْہَا جَذَعًا لَیْتَنِی أَکُوْنُ حَیًّا اِذْیُخْرِجُکَ قَوْمُکَ کہ کاش میں اس وقت مضبوط جوان ہوتا جب تیری قوم تجھے نکالے گی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی انہوں نے کہا کہ اس قسم کا کلام جب بھی کسی نے اپنی قوم کو سنایا ہے اس سے دشمنی کی گئی ہے.چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں.لَمْ یَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَاجِئْتَ بِہٖ اِلَّاعُوْدِیَ.(صحیح بخاری کتاب بد ء الوحی باب کیف کان بدء الوحی....) وَ كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ اور( جیسا کہ تو نے دیکھا ہے) اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا.اور( الٰہی) باتوں الْاَحَادِيْثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَ عَلٰۤى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَاۤ کی حقیقت بیان کر کے تجھے علم بخشے گا اور تجھ پر اور یعقوب کی تمام ( حقیقی) آل پر (اسی طرح) اپنے انعام
Page 404
اَتَمَّهَا عَلٰۤى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ١ؕ اِنَّ کو پورا کرے گا جیسا کہ اس نے( اس سے )پہلے تیرے دو بزرگوں ابراہیم اور اسحٰق پر پوراکیا تھا.رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌؒ۰۰۷ تیرا رب یقیناً بہت جاننے والا (اور) حکمت والا ہے.تفسیر.کَذٰلِکَ کے معنی یعنی جس طرح تو نے خواب دیکھی ہے اسی طرح تجھ سے اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا اور وہ بزرگی جس کا اس خواب میں وعدہ ہے آخر تجھے ملے گی.تعلیم تأویل الاحادیث کے دو معنے اور یہ جو فرمایا کہ خدا تعالیٰ تجھے خوابوں کی حقیقت بتائے گا اس کے دو معنے ہیں ایک یہ کہ خواب میں جو نظارہ دکھایا اسی طرح ظاہر میں کرکے دکھائے گا.دوسرے یہ کہ خوابوں کی تعبیر کرنے کا ملکہ عطا فرمائے گا.اتمام نعمت سے مراد يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ سے مراد مقام نبوۃ پر کھڑا کرنا ہے.یوسفؑ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نبوت عطا فرمائے گا اور ان کے ذریعہ سے آل یعقوب کو بزرگی عطا فرمائے گا یعنی انہیں ان پر ایمان لاکر اس نبوت میں حصہ لینے کی توفیق عطا ہوگی.بائبل اور قرآن کریم کے بیان میں چوتھا فرق.حضرت یعقوب ؑ رؤیا کو سن کر خوش ہوئے تھے اس آیت میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس میں اور بائبل کے بیان میں بھی اختلاف ہے.قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خواب پر یقین کیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا.لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب بیان کی ’’تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور اس سے کہا کہ یہ کیا خواب ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کہا کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کے تجھے سجدہ کریں گے اور اس کے بھائیوں کو رشک آیا لیکن اس کے باپ نے اس بات کو یاد رکھا (پیدائش باب۳۷ آیت ۱۰ و ۱۱) اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب سن کر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ڈانٹا حالانکہ ہر عقلمند انسان سمجھ سکتا ہے کہ بائبل کا یہ بیان خلاف عقل ہے کیونکہ کوئی معقول آدمی کسی کو خواب دیکھنے پر ڈانٹ نہیں سکتا کیونکہ خواب کا دیکھنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے.ہاں صرف ایک صورت ڈانٹنے کی ہوسکتی ہے کہ یہ خیال کیا جائے
Page 405
کہ خواب سنانے والے نے خواب نہیں دیکھا بلکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر بائبل کہتی ہے کہ یعقوبؑ نے کہا یہ ’’کیا خواب ہے جو تو نے دیکھا ہے.‘‘ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوبؑ نے یوسفؑ کو جھوٹا نہیں سمجھا.پس سچا سمجھتے ہوئے ڈانٹنا خلاف عقل ہے اور ہر عقلمند قرآن کریم کا ہی بیان درست اور صحیح سمجھے گا.علاوہ ازیں بائبل خود اپنے بیان کو رد کرتی ہے کیونکہ اس میں ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ یعقوبؑ نے اس خواب کو یاد رکھا.یاد رکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یعقوبؑ اس خواب کو سچا اور آسمانی سمجھتے تھے اور جب وہ اسے آسمانی خواب سمجھتے تھے تو کس طرح ممکن تھا کہ وہ اس خواب پر یوسف علیہ السلام کو ڈانٹتے جن کا خواب کے دیکھنے میں کوئی بھی دخل نہ تھا؟ آنحضرتؐ اور حضرت یوسفؑ کی چوتھی مماثلت اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رؤیا کو آسمانی قرار دیا اور اس پر ایمان لائے اور اسے اپنی قوم کی بزرگی کا موجب قرار دیا.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ورقہ بن نوفل نے آپؐ کی وحی کو سن کر اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے اور اسے موسیٰ کے الہام کی مانند قرار دے کر اپنی قوم کی بزرگی کا موجب تسلیم کیا اور کہا ھٰذَا النَّامُوْسُ الَّذِیْ نَزَّلَ اللہُ عَلٰی مُوسٰی یہ وہی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی(بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ ؐ).لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَ اِخْوَتِهٖۤ اٰيٰتٌ لِّلسَّآىِٕلِيْنَ۰۰۸ یوسف اور اس کے بھائیوں (کے واقعات) میں( حق کے) طالبوں کے لئے یقیناً کئی نشان( پائے جاتے )ہیں.تفسیر.یوسفؑ کےحالات بطور قصہ نہیں بلکہ بطور نشان بیان ہوئے ہیں یعنی جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی صداقت سمجھنے کے لئے کوشش کرتے ہوں ان کے لئے اس واقعہ میں نشانات ہیں.گویا یہ حالات بعینہٖ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو پیش آنے والے ہیں.یہ آیت کس طرح وضاحت سے ثابت کرتی ہے کہ یوسفؑ کا واقعہ بطور قصہ بیان نہیں ہوا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی صداقت کے متعلق جستجو کرنے والوں کے لئے نشانات بہم پہنچانے کی غرض سے بیان ہوا ہے.پس جو امور اس واقعہ میں بیان ہوئے ہیں وہ بطور نشان صداقت ہیں.
Page 406
ِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰۤى اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ (یعنی اس وقت کے واقعات میں) جب انہوں نے (یعنی یوسف کے بھائیوں نے ایک دوسرے سے) کہا( کہ) عُصْبَةٌ١ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِۚۖ۰۰۹ یوسف اور اس کا بھائی یقیناًہماری نسبت ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم ایک منضبط جماعت ہیں (اس معاملہ میں) ہمارا باپ یقیناً (کھلی) کھلی غلطی میں (پھنسا ہوا) ہے.حلّ لُغَات.عُصْبَۃٌ اَلْعُصْبَۃُ مِنَ الرِّجَالِ وَالْخَیْلِ وَالطَّیْرِ الْعِصَابَۃُ.وَالْعِصَابَۃُ اَلْجَمَاعَۃُ مِنَ الرِّجَالِ وَمِنَ الْخَیْلِ وَمِنَ الطَّیْرِ.وَقِیْلَ الْعَشَرَۃُ وَقِیْلَ مَابَیْنَ الْعَشَرَۃِ اِلَی الْاَرْبَعِیْن.عُصْبَۃٌ کے وہی معنے ہیں جو عِصَابَۃٌ کے ہیں.یعنی مطلق جماعت اور بعض کے نزدیک دس افراد کی جماعت اور بعض کے نزدیک دس سے لے کر چالیس تک کے افراد کی جماعت.(اقرب) مفسرین نے عشرہ والے معنے کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہ دس ہی تھے.عُصْبَۃٌ میں طاقت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے.یہ لفظ عصب سے نکلا ہے.گویا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام کرنے والے ہم، کمانے والے ہم مگر پیار کے لئے باپ کو یوسفؑ اور اس کا بھائی.آنحضرت ؐ اور حضرت یوسف ؑ میں پانچویں مشابہت تفسیر.یوسف ؑکی طرح آنحضرت ؐ پر لوگوں کا حسد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ساتھ بھی یہی واقعہ کئی رنگ میں پیش آیا ہے.چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زید ابن نفیل جو یہودی علماء سے توحید کا علم حاصل کرچکے تھے اسلام کے آنے سے پہلے شرک کے خلاف وعظ کیا کرتے تھے.ان سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ شرک کے خلاف وعظ تو میں کرتا رہا ہوں اگر کچھ بننا ہوتا تو میں بنتا.یہ شخص نبی کس طرح بن گیا(بخاری کتاب المناقب و سیرۃ النبی لابن ہشام ).یہی اعتراض آپؐ کی نبوت پر یہود و نصاریٰ کو تھا.کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ خدا کے دین کے حامل تو ہم ہیں یہ انعام کا مستحق کس طرح ہو گیا.بلکہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ کے دلوں میں بھی یہ خیال عام تھا کہ ہم میں سے جو بڑے لوگ ہیں ان پر یہ کلام کیوں نازل نہ ہوا.چنانچہ سورہ زخرف میں فرماتا ہے وَ قَالُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ
Page 407
الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ.(الزخرف:۳۲) اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں یہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر نازل نہ ہوا.یعنی انہیں حسد آتا ہے کہ اس کمزور آدمی کو خدا تعالیٰ نے کیوں اپنے فضل کے لئے چن لیا جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ (الزخرف:۳۳) کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو خود تقسیم کرنا چاہتے ہیں.لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ یعنے چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے کاموں کی وجہ سے ہم سے پیار کیا جاتا.یوسفؑ چھوٹا اور نکما ہے اس سے محبت کرنا اور ہم سے نہ کرنا صریح غلطی ہے.یہ بات بتارہی ہے کہ ان کو اس کے خلاف سخت غصہ تھا.ا۟قْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ (اس لئے یا تو) یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی اور ملک میں (دور) پھینک دو( ایسا کرو گے تو) تمہارے باپ کی توجہ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ۰۰۱۰ تمہارے لئےفارغ ہو جائے گی اور (اس فعل سے ڈرنے کی وجہ نہیں) اس کے بعد (توبہ کر کے) تم (پھر )ایک نیک گروہ ہو جاؤ گے.حلّ لُغَات.صَلَحَ الشَّیْءُ یَصْلُحُ وَیَصْلَحُ صَلَاحًا وَصُلُوْحًا وَصَلَاحِیَۃً ضِدُّ فَسَدَ اَوْزَالَ عَنْہُ الْفَسَادُ.یُقَالُ صَلُحَتْ حَالُ فُلَانٍ.درست اور ٹھیک ہو گیا.اس کی خرابی اور بدحالی دور ہو گئی.الرَّجُلُ فِی عَمَلِہٖ لَزِمَ الصَّلَاحَ.نیکوکار ہو گیا.(اقرب) تفسیر.نیک صحبت کا اثر نیک صحبت کس طرح دل پر اثر کرتی ہے.ایک خطرناک جرم کا ارتکاب کرنے لگے ہیں لیکن پھر بھی گناہ کا خوف دل میں ہے اور اس خوف کا اثر دل سے مٹانے کے لئے یہ بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ پھر توبہ کرلیں گے.نفس کا ایک خطرناک دھوکہ یہ دھوکا بہت سے لوگوں کو لگا ہوا ہوتا ہے.وہ خیال کرتے ہیں کہ پھر توبہ کر لیں گے حالانکہ زندگی کا اعتبار کیا؟ خواہ کس قدر پختہ نیت بھی توبہ کرنے کی ہو لیکن موت آجائے یا دماغ میں فتور آجائے یا عادت پڑ جائے تو پھر توبہ کا ارادہ کس طرح پورا ہوسکتا ہے.قرآن مجید اور بائبل کے بیانات اس واقعہ میں بھی مختلف ہیں.قرآن کریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوسفؑ کے
Page 408
بھائیوں نے پہلے مشورہ کیا اور مشورہ کے بعد وہ یوسف علیہ السلام کو باہر لے جانے کی کوشش کرنے لگے.مگر بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اچانک یوسفؑ کو آتے دیکھا تو فوراً قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے.چنانچہ بائبل میں لکھا ہے ’’اور جونہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا اس سے پہلے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا اور ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو یہ صاحبِ خواب آتا ہے سو آؤ ہم اب اسے مار ڈالیں.اور کسی کنوئیں میں ڈال دیں اور کہیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوگا.(پیدائش باب۳۷ آیت ۱۸ لغایت ۲۰) جرائم کی تحقیقات کرنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس اختلاف میں قرآن مجید کا بیان ہی قرین قیاس ہے.یونہی کھڑے کھڑے یکدم قتل کرنے کو تیار ہو جانا یا عادی ڈاکوؤں کا کام ہے یا پاگلوں کا.حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اپنے گھر میں شریفانہ زندگی بسر کرتے تھے وہ یکایک ایسے بھیانک فعل کے لئے تیار نہیں ہوسکتے تھے.پس ان کا اس طرح قتل کے لئے آمادہ ہو جانا بتلاتا ہے کہ وہ پہلے مشورہ کرچکے تھے.فوراً تحریک کرنے والے کو کیا یہ ڈر نہ آتا کہ اتنی بڑی بات میں اگر بھائی ہم خیال نہ ہوئے تو میرا کیا حشر ہوگا.ان کا قول وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَکہ محرک جرم جب راستہ سے ہٹ جائے گا تو پھر تم نیک ہو جاؤ گے بھی بتا رہا ہے کہ وہ عادی مجرم نہ تھے اور ان کی فطرت اس کام کو ناپسند کرتی تھی.پس عقل کی رو سے قرآن مجید کا بیان ہی صحیح اور واقعات کے مطابق ہے.آنحضرتؐ اور حضرت یوسفؑ میں چھٹی مماثلت حضرت یوسف ؑ کی طرح آنحضرت ؐ کے خلاف قتل کا منصوبہ وغیرہ اس منصوبۂ قتل میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہت ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ١ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.(الانفال :۳۱) یعنی یاد کر جبکہ دشمن منصوبے کرتے تھے کہ تجھے کہیں قید کر دیں یا قتل کردیں یا تجھے نکال دیں اور وہ اب بھی ایسے منصوبے کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پختہ تدبیریں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر زیادہ اچھی ہوتی ہے.پس جس طرح یوسف علیہ السلام کی نسبت قتل اور کسی دوسرے علاقہ میں پھینک دینے کا منصوبہ کیا گیا تھا اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے متعلق بھی منصوبہ کیا گیا.
Page 409
قَالَ قَآىِٕلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَ اَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ (اس پر) ان میں سے ایک بولنے والے نے کہا( کہ) تم یوسف کو قتل نہ کرو اور اگر( بہرحال) تم نے (کچھ )کرنا (ہی) الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ۰۰۱۱ ہے تو اسے (کسی) گہرے کنوئیں کی تہ میں ڈال دو کسی قافلہ کا کوئی شخص اسے (دیکھ کر )اٹھائے گا (اور بغیر جان لینے کے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا ) حلّ لُغَات.غَیَابَۃٌ اَلْغَیَابَۃُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ مَاسَتَرَکَ مِنْہُ.غَیَابَۃٌ.ہر چیز کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو اسے نظروں سے غائب کردے.وَمِنَ الْجُبِّ وَالْوَادِیِ قَعْرُہٗ اور کنوئیں یا وادی کا غیابہ اس کے گہراؤ اور تہہ کو کہتے ہیں.پس غیابۃ کا لفظ وادی یا جُبّ وغیرہ کی طرح کی جگہ کے نام کی طرف مضاف ہوکر استعمال ہوتا ہے اور اس کی تہہ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے.وَوَقَعْنَا فِی غَیَابَۃٍ أَیْ ھَبْطَۃٍ مِنَ الْاَرْضِ.زمین کا گہرا حصہ اَلْقَبْرُ.قبر.(اقرب) اَلْجُبُّ اَلْجُبُّ اَلْبِئْرُاَوِالْبِئْرُ الْکَثِیْرُ الْمَاءِ الْبَعِیْدۃَ الْقَعْرِ.مطلق کنواں یا بہت پانی والا اور بہت گہرا کنواں وَ فِی الْمِصْبَاحِ وَالْجُبُّ بِئْرٌ لَمْ تُطْوَ.ایسا کنواں جس کے گرد منڈیریں وغیرہ نہ ہوں اور ویراں پڑا ہو.(اقرب) سَیَّارَۃٌ.اَلسَّیَّارَۃُ مُؤَنَّثُ السَّیَّارِ.سیّارہ.سیّار کی مؤنث ہے جس کے معنے ہیں کَثِیْرُالسَّیْرِ بہت سیر کرنے والا.اَلْقَافِلَۃُ.قافلہ.وَاَصْلُہَا الْقَوْمُ یَسِیْرُوْنَ اور اس کے اصل معنے ایسی جماعت کے ہیں جو سفر کررہی ہو.(اقرب) تفسیر.یعنی اگر تم یوسف سے ضرور ہی مخالفت کرنا چاہتے ہو تو بھی اسے قتل نہ کرو بلکہ اسے گھر سے نکالنے کی تدبیر کرو.ساتویں مماثلت حضرت یوسفؑ کی طرح آنحضرتؐ کے قتل کے منصوبہ کی بعض اہل مکہ کی طرف سے مخالفت جس طرح یوسفؑ کے قتل کے بارہ میں بعض لوگوں نے مخالفت کی تھی ایسا ہی مکہ کے بعض لوگوں نے
Page 410
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں کفار کی مخالفت کی اور کہا کہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ بعض نے تو اس معاہدہ کو زور سے تڑوا دیا جو آپؐ کو اور آپ کے اتباع کو فاقے مارنے کے متعلق کیا گیا تھا.(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان حدیث نقص الصحیفۃ).قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَ اِنَّا لَهٗ (چنانچہ) انہوں نے (باپ سے جا کر)کہا ا ےہمارے باپ آپ کو (ہمارے متعلق) کیا (خدشہ) ہے کہ یوسف لَنٰصِحُوْنَ۰۰۱۲ کے متعلق آپ ہم پراعتماد نہیں کرتے.حالانکہ ہم یقیناً اس سے (دلی) خلوص رکھتے ہیں.حلّ لُغَات.اَ مَّنَ.تَأْمَنَّا اَمِنَہٗ وَاَمَّنَہٗ واٰمَنَہٗ وَاسْتَأْمَنَہٗ.اَیْ جَعَلَہٗ اَمِیْنًا.اسے امین بنایا.(تاج العروس) نَصَحَ نَصَحَ الشَّیْءُ نَصْحًا وَنُصُوْحًا.خَلَصَ ہر غل و غش اور کھوٹ سے پاک و صاف ہوا.نَصَحَتْ تَوْبَتُہُ نُصُوْحًا خَلَصَتْ مِنْ شَوَائِبِ الْعَزْمِ عَلَی الرَّجُوْعِ.توبہ عہدشکنی اور خلاف ورزی کے خیالات کی آمیزش سے بکلی پاک ہوئی.اَلثَّوْبُ اَنْعَمَ خِیَاطَتَہٗ وَ لَمْ یَتْرُکْ فَتْقًا وَلَا خِلَالًا.شُبِّہَ ذٰلِکَ بِالنَّصْحِ.کپڑا ایسا سیا کہ اس میں کوئی شگاف اور رخنہ وغیرہ نہ چھوڑا.جیسے خلوص کی حالت میں کوئی مخالف خیال باقی نہیں رہتا.الْعَمَلَ اَخْلَصَہٗ عمل کو خالص کیا.الْعَسْلَ صَفَّاہُ.شہد کو پاک و صاف کیا.(اقرب) تفسیر.بائبل کے اور قرآن کریم کے بیان میں چھٹا اختلاف بائبل کا بیان ہے کہ ’’اور اس کے بھائی اپنے باپ کے گلے چراتے سکم کو گئے.تب اسرائیل نے یوسف کو کہا کیا تیرے بھائی سکم میں نہیں چراتے ہیں.آمیں تجھے ان کے پاس بھیجوں اس نے اسے کہا کہ میں حاضر ہوں‘‘.(پیدائش باب۳۷ آیت ۱۲،۱۳) یعنی باپ نے خود یوسف علیہ السلام کو تحریک کرکے بھائیوں کے پاس بھیجا.مگر قرآن مجید یہ بتلاتا ہے کہ بھائیوں نے قتل کا مشورہ کیا اور پھر باپ سے اجازت چاہی کہ باپ اسے ان کے ساتھ بھیجے.بائبل کایہ بیان خود بائبل کی رو سے غلط ہے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی کاوش کو جانتے تھے انہیں معلوم تھا کہ باقی بھائی یوسف کو کس نظرسے دیکھتے ہیں اور بائبل میں لکھا ہے ’’اور اس کے بھائیوں نے یہ دیکھ کے کہ
Page 411
ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے اسے (یعنی یوسف کو) زیادہ پیار کرتا ہے اس کا کینہ پیدا کیا اور اس سے محبت کی بات نہ کرسکتے تھے.‘‘ (پیدائش باب۳۷ آیت۴) اس صورت میں یہ بالکل غیرطبعی بات ہے کہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے پاس بھیجیں.پس بائبل کا بیان غلط ہے اور قرآن مجید کا بیان ہی صحیح ہے.حضرت یوسف کی عمر اس واقعہ کے وقت اس آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت قریباً گیارہ بارہ سال کی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ الفاظ اتنی ہی عمر کے بچے کے متعلق زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں.مگر بائبل کے بیان کے مطابق وہ اس وقت ۱۷ یا ۱۸ سال کے ہوچکے تھے (پیدائش باب ۳۷ آیت ۲)لیکن یہ بات غلط ہے جیسا کہ آگے اس کی تحقیق آئے گی.اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۰۰۱۳ کل اسے ہمارے ساتھ( سیر کے لئے باہر) بھیجئےوہ ( وہاں) کھلا کھائے (پیئے) گا اور کھیلے گا.اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے.حلّ لُغَات.رَتَعَ رَتَعَتِ الْمَاشِیَۃُ فِی الْمَکَانِ رَتْعًا وَرُتُوْعًا وَرِتَاعًا اَکَلَتْ وَشَرِبَتْ مَا شَاءَ تْ فِی خَصْبٍ وَّسَعَۃٍ.جانوروں نے عمدہ چراگاہ سے جو کچھ چاہا کھایا اور پیا.وَالْقَوْمُ اَکَلُوْا مَاشَاءُوا فِی رَغَدٍ.لوگوں نے جو چاہا بافراغت کھایا.وَیُقَالُ خَرَجْنَا نَرْتَعُ وَنَلْعَبُ.اَیْ نُنْعِمُ وَنَلْہُوْ.اور نَرْتَعُ وَ نَلْعَبُ کے معنے محاورہ میں عیش کرنے اور کھیلنے کے ہوتے ہیں.(اقرب) تفسیر.قرآن کریم کے اور بائبل کے بیان میں ساتواں اختلاف.یوسف کے بھائی کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھیتی بھی کرتے تھے.بائبل کہتی ہے کہ وہ صرف جانور ہی چراتے تھے.لیکن بائبل میں جو پہلا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے اس میں ان کے بھائیوں کے پولے باندھنے کا ذکر ہے(پیدائش باب ۳۷ آیت ۷) اور ایک چھوٹا بچہ جو گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلا اور جو شہر میں نہیں رہتا بلکہ اس کا خاندان باقی دنیا سے الگ زندگی بسر کررہا ہے ایسی خواب نہیں دیکھ سکتا تھا جس کا نظارہ اس کی آنکھوں کے آگے نہ آچکا ہو.پس اس خواب سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا بیان ہی صحیح ہے.یوسف کی حفاظت کا وعدہ بھی ان کی اس وقت کی عمر پر روشنی ڈالتا ہے اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ سے بھی ظاہر
Page 412
ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک ان کی عمر ابھی چھوٹی ہی تھی ورنہ جنگل میں رہنے والے سترہ برس کے نوجوان زمیندار کے لئے غیر کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی.قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَ اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ اس نے (یعنے یعقوب نے) کہا تمہارا اسے (اپنےساتھ) لے جانا مجھے یقیناً فکر مند کر تا ہے اور میں (اس بات سے الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ۰۰۱۴ بھی) ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسی حالت میں کہ تم اس سے غافل ہو اسے (کوئی) بھیڑ یا (ہی نہ آ کر) کھا جائے.تفسیر.حضرت یعقوب ؑ کو یہ خوف ہونا بھی حضرت یوسف ؑ کو اس وقت بچہ ثابت کرتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بات کو خیال کرکے بھی میرا دل افسردہ ہوتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو.اس قول سے ایک تو اس امر کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت چھوٹی تھی دوسرے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو الہاماً یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ایسا منصوبہ کررہے ہیں اس لئے انہوں نے وہی الفاظ استعمال کئے جو بھائیوں نے بطور بہانہ کے تجویز کئے تھے.قَالُوْا لَىِٕنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّاۤ اِذًا انہوں نے کہا اگر اس (بات) کے باوجود (بھی) کہ ہم ایک منضبط جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا جائے تو( خدا کی لَّخٰسِرُوْنَ۰۰۱۵ قسم) اس صورت میں ہم یقیناً گھاٹے میں پڑنے والے ہوں گے.تفسیر.حسد اور بغض انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے اس واقعہ سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ حسد اور بغض انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے.یوسف علیہ السلام کے د س بھائیوں میں سے دانی اور تفتانی کو تو سخت شرم کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی لونڈی کے بیٹے تھے جب ان کے اولاد
Page 413
نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی وہ لونڈی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دی کہ تا ان کی نسل چلے اور انہوں نے اس کے بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیا اور پہلے کا نام دانی رکھا کہ مجھے بھی ایک بیٹا دیا گیا اور دوسرے کا نام تفتانی کہ میں اس کے ذریعہ سے اپنی بہن پر غالب آئی.یہ بھی میرا ہی بیٹا ہے (پیدائش باب ۳۰ آیت ۱ تا ۸)پھر ان لڑکوں کو خود حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ نے ہی پرورش کیا تھا مگر ان کی سیاہ دلی کو دیکھو کہ اپنی محسنہ کے بیٹے کے قتل کے منصوبے میں شریک ہو گئے.فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَ اَجْمَعُوْۤا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ١ۚ پھر جب وہ اسے لے گئے اور( جا کر) انہوں نے اسے (کسی) گہرے کنوئیں کی تہ میں ڈالنے کا متفقہ فیصلہ کر لیا وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَ هُمْ لَا ( تو ادھر انہوں نے اپنا ارادہ پورا کیا)اور (ادھر )ہم نےاس کی طرف وحی (کے ذریعہ سے یہ بشارت نازل) کی کہ يَشْعُرُوْنَ۰۰۱۶ تو( محفوظ رہے گااور) انہیں ان کے اس کام سے آگاہ کر ے گا اور وہ (اس بات کو) نہیں سمجھتے تھے.تفسیر.مطلب یہ کہ آج ان کو پتہ نہیں کہ ایسا برا سلوک یہ کس کےساتھ کررہے ہیں مگر جب تیرے سامنے کھڑے ہوں گے تو انہیں خوب معلوم ہو جائے گا.اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت عجز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس وقت ان کے بھائیوں کے ذہن میں بھی نہ آسکتا تھا کہ یہ کتنے بڑھ جائیں گے.آٹھویں مشابہت آنحضرت ؐ کو بھی ایک کنوئیں کی سی جگہ میں اترنا پڑا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اس کنوئیں کے واقعہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے.آپؐ کو بھی کفار سے تنگ آکر مکہ سے نکلنا پڑا اور ان کے تعاقب کی وجہ سے غارثور میں چھپنا پڑا(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام ھجرۃ الرسول ) جو باولی کی طرح پہاڑ کی ایک غار ہے.فرق صرف یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غار میں گھسنا پڑا.یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس بارہ میں مشابہت اس واقعہ سے ہو جبکہ آپؐ کو تین سال تک مکہ کے پاس ایک وادی میں محصور کر دیا گیا تھا.
Page 414
نویں مشابہت آنحضرت ؐ کوبھی ظالم بھائیوں کا مجرم بن کر سامنے آنا پہلے سے دکھایا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبل از وقت بتا دیا گیا تھا کہ آپؐ کے سامنے آپؐ کے بھائی مجرم بن کر پیش ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا تھا.مثال کے طورپر قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ( القصص:۸۶) وہ خدا جس نے یہ قرآن تجھ پر عمل کے لئے اتارا ہے ضرور تجھے ایک دن اس شہر کی طرف جو لوگوں کا مرجع ہے واپس لائے گا.یعنے یہاں سے نکلنے کے بعد پھر تم کامیاب واپس آؤ گے.وَ جَآءُوْۤ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَؕ۰۰۱۷ اور عشاء کے وقت وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے.حلّ لُغَات.الْعِشَاءُ اَلْعِشَاءُ اَوّلُ الظَّلَامِ.رات کی تاریکی کا ابتدائی حصہ.وَقِیْلَ مِنَ الْمَغْرِبِ اِلَی الْعَتَمَۃِ.اور بعض کہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے لے کر تاریکی کے پورے طور پر چھا جانے تک کا درمیانی وقت وَقِیْلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ اِلٰی طُلُوْعِ الْفَجْرِ.اور بعض کہتے ہیں کہ سورج کے ڈوبنے سے لے کر پو پھوٹنے تک کا وقت عشاء ہی ہے.(اقرب) قَالُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ (اور) کہا( کہ) اے ہمارے باپ (یقین جانیے) ہم جاکر( کھیلنے اور) مقابلۃً دوڑنے لگے اور یوسف کو ہم اپنے مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ١ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا سامان کے پاس چھوڑ گئے تو( خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ) اسے (ایک) بھیڑیا کھا گیا اور (یہ تو ہم جانتے ہیں کہ) آپ صٰدِقِيْنَ۰۰۱۸ ہماری بات (کودرست) نہیں ماننے کےگو ہم (اس میں بالکل) سچے( ہی کیوں نہ) ہوں.تفسیر.حضرت یوسفؑ کی خورد سالی پرتَرَكْنَا يُوْسُفَاور اَكَلَهُ الذِّئْبُ کی دلالت تَرَكْنَا
Page 415
يُوْسُفَاوراَكَلَهُ الذِّئْبُ سے بھی ظاہر ہوتاہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ابھی چھوٹی تھی ورنہ سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا ہر قسم کی کھیلوں میں شامل ہوسکتا تھا اور بھیڑیا بھی ایک جوان آدمی پر جس کے پاس ہتھیار ہوں حملہ نہیں کیا کرتا سوائے اس کے کہ بھیڑیوں کا ایک گلہ ہو لیکن فلسطین کا علاقہ ایسا نہیں جہاں بھیڑیئے گلوں کی صورت میں پھرتے ہوں.برادران یوسف کا یہ بیان بھی ظاہر کرتاہے کہ وہ عادی مجرم نہ تھے وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی عادی مجرم نہ تھے ورنہ وہ یہ فقرہ نہ کہتے جس سے ان کے جرم کاراز فاش ہو جاتا ہے.عادی مجرم کبھی اپنے جرم کو ظاہر نہیں ہونے دیتا.لیکن ان کے منہ سے تو بے اختیار نکل گیا کہ اگر ہم سچے بھی ہوں تو آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اور اس طرح انہوں نے خود ہی اپنے جھوٹ پر سے پردہ اٹھا دیا.وَ جَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ١ؕ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ اور( اسے یقین دلانے کے لئے وہ) اس کے کرتے پر جھوٹا خون لگا لائے (تھے.جسے دیکھ کر) اس نے کہا (یہ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا١ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ١ؕ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ بات درست نہیں) بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لئے کسی (بری) بات کو خوبصورت کر کے دکھلا یا ہے( جسے تم کر عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ۰۰۱۹ گزرے ہو)اب اچھی طرح صبر کرنا (ہی میرے لئے مناسب) ہے اور جو بات تم بیان کرتے ہو اس( کے تدارک) کے لئے اللہ (تعالیٰ) ہی سے مدد مانگی جاسکتی ہے (اور اسی سے مانگی جائے گی.) حلّ لُغَات.سَوَّلَ.سَوَّلَتْ سَوَّلَ لَہُ الشَّیْطٰنُ اَغْوَاہُ وَسَھَّلَ لَہٗ.اسے گمراہ کیا اور برے کام کے ارتکاب کو اس کی نظر میں معمولی بات کرکے دکھایا.مِنَ السَوَلِ اَیْ الْاِسْتِرْخَاءُ.یہ لفظ سَوَلَ سے ہے جس کے معنے ڈھیلا ہوجانے کے ہیں.یُقَالُ ھٰذَا مِنْ تَسْوِیْلَاتِ الشَّیٰطِیْنِ وَمَا تَطْلُبُہٗ وتَسْأَلُہٗ.یعنی شیطان کی تسویلات سے مراد اس کی گمراہ کن تحریکیں ہیں.سَوَّلَتْ لَہُ نَفْسُہٗ کَذَازَیَّنَتْہُ لَہٗ وَسَھَّلَتْہٗ لَہٗ وَ ھَوَّ نَتْہُ.اس کے نفس نے اس کے لئے اس کام کو خوبصورت کرکے یا اسے ایک معمولی بات قرار دے کر اور آسان کرکے
Page 416
دکھایا.(اقرب) فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ.اس جملہ میں حذف واقع ہوا ہے.اور پورا جملہ تین طرح ہوسکتا ہے.(۱) یہ کہ فَصَبْرِیْ صَبْرٌجَمِیْلٌ.میرا صبر صبرِجمیل ثابت ہوگا.میں ہرگز نہ گھبراؤں گا.(۲) اَمْرِیْ صَبْرٌ جَمِیْلٌ.میرا کام صبرجمیل ہوگا.(۳) یہ کہ صَبْرٌجَمِیْلٌ خَیْرٌ.صبرجمیل کرنا ہی بہتر ہے.گویا یا مبتداء محذوف مانا جائے گا.یا خبر محذوف مانی جائے گی.مُسْتَعَانٌ.مُسْتَعَانٌ اسم مفعول کا صیغہ ہے اِسْتَعَانَ سے اور اس کے معنے ہیں ’’وہ وجود جس سے مدد طلب کی جائے.‘‘ تفسیر.آٹھواں اختلاف یعقوب ؑ کو یوسفؑ کے زندہ موجود ہونے کا علم تھا بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے پھاڑے جانے کا یقین ہو گیا تھا.جیسا کہ لکھا ہے ’’اس (یعقوب) نے اسے (کرتہ کو) پہچانا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی قبا ہے.کوئی برا درندہ اسے کھا گیا اور یوسف بے شک پھاڑا گیا.‘‘ (پیدائش باب ۳۷ آیت ۳۳)مگر قرآن مجید کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو محض فریب سمجھا بلکہ ان کے بیان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد چاہی اور مدد چاہنا بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابھی امید تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں.ورنہ مُسْتَعَانٌ کا لفظ کہنا بے فائدہ تھا.اس اختلاف میں بھی بائبل اپنی غلطی کا آپ اقرار کرتی ہے اس اختلاف میں بھی قرآن کریم کے بیان کی صداقت خود بائبل ہی کے دوسرے حوالہ جات سے ہوجاتی ہے.چنانچہ پیدائش باب۴۴ میں لکھا ہے کہ جب مصر میں حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا تو یہودا یوسف کے سامنے آیا اور اس نے کہا ’’میرے باپ نے ہم کو کہا تم جانتے ہو کہ میری جورو مجھ سے دو بیٹے جنی ایک مجھ سے جدا ہوا ا ور میں نے کہا یقیناً وہ پھاڑا گیا اور میں نے اسے اب تک نہیں دیکھا.‘‘ (آیت ۲۷ ،۲۸) حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں نے اسے اب تک نہیں دیکھا صاف بتا رہا ہے کہ وہ اسے زندہ سمجھتے تھے ورنہ اگر انہیں یقین ہو جاتا کہ وہ پھاڑا گیا ہے جیسا کہ بائبل نویس نے یہاں بھی لکھ دیا ہے تو ان کا یہ قول کچھ معنے نہیں رکھتا.پس اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا بیان ہی درست ہے اور حضرت یعقوبؑ حضرت یوسفؑ کو زندہ ہی سمجھتے تھے.طالمود سے بھی قرآن کریم کے بیان کی ہی تائید ہوتی ہے طالمود بھی قرآن مجید کے بیان کی تائید کرتی ہے.اس میں بھی لکھا ہے کہ یعقوب کو ان کی بات کا یقین نہ آیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے.حتیٰ کہ وہ بھائی ایک
Page 417
بھیڑیا پکڑ لائے.بھیڑیئے نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو کیسے کھاسکتا تھا.حالانکہ آج تو خود میرا بیٹا گم ہو گیا تھا.پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مختلف تفاول نکالتے رہتے تھے.آخر خدا نے انہیں خواب میں بتایا کہ وہ زندہ ہے.(جیواش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Joseph) طالمود کا یہ بیان خواہ کس قدر ہی خلافِ عقل ہو مگر یہودا کے قول سے مل کر اس سے یہ امر یقیناً ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت یعقوبؑ اپنے بیٹوں کے بیان کو سچا نہیں سمجھتے تھے.دسویں مماثلت آنحضرتؐ کے قتل کے متعلق بھی خبر مشہور کر دی گئی تھی جس طرح یوسفؑ کے بھائیوں نے جھوٹے طور پر یہ کہہ دیا کہ یوسفؑ مارا گیا ایسا ہی کفارِ مکہ نے بھی کہا.چنانچہ جنگِ احد کے موقع پر ابوسفیان نے اعلان کر دیا اِنَّا قَتَلْنَا مُـحَمَّدًا ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مار دیا ہے.اور مکہ میں آکر بھی یہی خبر مشہور کردی.ہاں اتنا فرق ہے کہ انہوں نے قتل کو بھیڑیئے کی طرف منسوب کیا اور کفار مکہ نے اپنی طرف.وَ جَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ١ؕ قَالَ اور (اتنے میں )ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے (آدمی )کوبھیجا اور اس نے (اسی کنوئیں پر جا کر) يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ١ؕ وَ اَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً١ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ اپنا ڈول ڈالا.(اور جب اسے کنوئیں میں ایک لڑکا نظر آیا تو) اس نے (قافلہ والوں سے) کہا اے( قافلہ والو!لو) بِمَا يَعْمَلُوْنَ۰۰۲۰ خوش خبری (سنو اور دیکھو )یہ ایک لڑکا ہے اور انہوں نے اسے ایک تجارتی مال سمجھتے ہوئے چھپا لیا اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے اللہ( تعالیٰ) خوب جانتا تھا.حلّ لُغَات.وَارِدٌ اَلْوَارِدُ اَلَّذِیْ یَتَقَدَّمُ اِلَی الْمَاءِ.قافلہ کا وہ آدمی جو پہلے پہنچ کر پانی کا انتظام کرے.اَلَّذِیْ یَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ فَیَسْقِیْ لَہُمْ جو قافلہ سے پہلے پہنچ کر پانی وغیرہ کا انتظام کرے.اَرْسَلُوْا وَارِدَھُمْ اَیْ سَاقِیَہُمْ.ساقی.پانی پلانے والا.جس کے ذمہ پانی کا فراہم کرنا ہو.(مفردات) اَلْوَارِدُ.اَلسَّابِقُ پہلے پہنچنے والا.اَلْوَارِدَۃُ: اَلْقَوْمُ یَرِدُوْنَ المَاءَ.گھاٹ پر اتر کر پانی لانے والے لوگ.(اقرب)
Page 418
یَابُشْرٰی جیسے ہمارے ہاں واہ واہ کہتے ہیں ویسے ہی عربی زبان میں استعجاب اور عظمت کے لئے بطور مبالغہ یَابُشْرٰی کہتے ہیں.یَاوَیْلَتٰی اور یٰحَسْرتٰی بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں.اَلْبِضَاعَۃُ.طَائِفَۃٌ مِّنَ الْمَالِ تُعَدُّ لِلْتِّجَارَۃِ کچھ مال جو تجارت کے لئے تیار کیا جائے.(اقرب) تفسیر.اللہ تعالیٰ کا یوسف ؑ کے لئے اس بے کسی کی حالت میں جنگل میں سامان پیدا کرنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسا وفادارانہ سلوک کرتا ہے.جنگل کے ایک کنوئیں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں ڈال دیا.لیکن معاً اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا کر دیا کہ ایک قافلہ آ گیا اور انہوں نے پانی لینے کے لئے ایک آدمی بھیجا اور وہ آدمی اسی کنوئیں پر آگیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے ڈال دیا تھا.اہل قافلہ کے دلوں میں یوسف کی توقیر اَسَرُّوْهُ بِضَاعَةًسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے قیمتی چیز سمجھتے تھے اور یوسف علیہ السلام کی شکل سے ہونہاری کے آثار ظاہر تھے.وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ١ۚ وَ كَانُوْا فِيْهِ اور( اس کے بعد جب برادران یوسف کو اس کا علم ہوا تو) انہوں نے (اپنا غلام بنا کر) کچھ تھوڑی (سی) قیمت مِنَ الزَّاهِدِيْنَؒ۰۰۲۱ یعنی چندگنتی کے درہموں میں (اسی قافلہ والوں کے پاس اسے) بیچ دیا اوروہ اس (قیمت) سے بالکل بے رغبت تھے.تفسیر.یہ بے رغبتی رکھنے والے یوسف کے بھائی تھے مراد یہ کہ جب اس قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا تو بھائیوں کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے اپنا غلام ظاہر کرکے انہیں بیچ دیا.بائبل سے ثابت ہے کہ بیس روپے پر بیچا تھا.(پیدائش باب ۳۷ آیت ۲۸) قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ بیچنا روپیہ کمانے کی نیت سے نہ تھا بلکہ صرف دکھاوے کے لئے تھا.معلوم ہوتا ہے وہ ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے یوسف کو چھڑانے کی کوشش نہ کی تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ آزاد ہے.اور شاید اس کو گھر پہنچا دیں.اس وجہ سے اسے غلام بتایا اور نکما ظاہر کرکے ادنیٰ قیمت پر اسے بیچ دیا تاکہ قافلہ کو کوئی شبہ نہ ہو ورنہ فروخت کرکے کوئی قیمت لینا ان کے مدنظر نہ تھا.شَرَوْهُکے معنے خریدنے کے بھی ہوسکتے ہیں شَرَوْهُ کے معنے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ انہوں نے خریدا اور اس
Page 419
صورت میں ضمیر قافلہ والوں کی طرف پھیری جائے گی اور مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا.بیچنے والے اہل قافلہ نہیں ہو سکتے قرآن مجید کے بیان سے یہ ظاہر ہے کہ اس جگہ پر بیچنے والے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں.اہل قافلہ نہیں کیونکہ اہل قافلہ کے متعلق تو فرمایا ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پایا تو اَسَرُّوْہُ بِضَاعَۃً اسے قیمتی چیز سمجھ کر چھپا لیا لیکن بعد میں فرماتا ہے كَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ وہ اس کے متعلق کوئی رغبت ظاہر نہیں کرتے تھے.پس معلوم ہوا کہ بیچنے والے قافلہ والے نہ تھے.بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے.بائبل کی ٹھوکر کا ثبوت خود بائبل میںسے ۙاس واقعہ کے متعلق بھی بائبل اور قرآن مجید کے بیان میں اختلاف ہے.بائبل تو کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنوئیں میں ڈال کر کھانا کھانے بیٹھے تو انہیں ایک اسماعیلی قافلہ نظر آیا.اس پر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہیں نکال کر قافلہ کے پاس بیچ دیں.چنانچہ لکھا ہے.’’سو انہوں نے یوسف کو کھینچ کے کنوئیں سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ بیس روپے کو بیچا.‘‘ (پیدائش باب ۳۷ آیت ۲۸) مگر قرآن مجید کے رو سے یوسف علیہ السلام کو کنوئیں سے نکالنے والے خود قافلہ کے لوگ تھے.بائبل کی بات کوغلط ثابت کرنے کے لئے اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ بائبل نے انہی تین چار آیتوں میں سخت متضاد بیان دیئے ہیں.اسی باب کی آیت ۲۵ اور ۲۷ میں اس قافلہ کو اسماعیلیوں کا قافلہ قرار دیا ہے مگر آیت ۲۸ میں انہیں مدیانی سوداگر ظاہر کیا ہے.لیکن اسی آیت کے دوسرے حصہ میں پھر انہیں اسماعیلی کہا ہے.حالانکہ مدیانی اور اسماعیلی نسل میں بہت بڑا فرق ہے.قرآن مجید کے بیان کی تصدیق طالمود سے بھی ہو جاتی ہے ان چار آیتوں میں غلطی کرنے والی اور قدم قدم پر ٹھوکر کھانے والی کتاب کو ہم کیونکر قرآن پر حاکم ٹھہرا سکتے ہیں؟ پھر قرآن مجید کے بیان کی تصدیق طالمود سے بھی ہوجاتی ہے.جیواش انسائیکلوپیڈیا میں یوسف لفظ کے نیچے طالمود کا بیان بعینہٖ وہی درج ہے جو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے.پھر طالمود مرتبہ ایچ پولائینو کے صفحہ ۷۴،۷۵ پر لکھا ہے ’’مگر واقع یوں ہوا کہ جب وہ لوگ یوسف کے متعلق گفتگو کررہے تھے ایک مدیانیوں کا قافلہ جو سفر کررہا تھا پانی کے کنوئیں کی تلاش میں آنکلا.اتفاقاً وہ اسی کنوئیں پر آکر اترے جس میں یوسف کو چھپایا گیا تھا اور وہ ایک خوبصورت اور ہوشیار لڑکے کو اس میں دیکھ کر حیران رہ گئے.
Page 420
انہوں نے یوسف کو کنوئیں سے نکالا اور اپنے ساتھ لے چلے.جب وہ یعقوب کے بیٹوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے یوسف کو دیکھ لیا اور پکارے دیکھو تم اس غلام کو جسے ہم نے کنوئیں میں اس کی نافرمانی کی وجہ سے ڈالا تھا کیوں چرا کر لے چلے ہو.لاؤ اسے ہمارے حوالہ کرو.‘‘ اس حوالہ کا مضمون قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے.اور بائبل جس نے اس واقع کے بیان کرتے وقت تین چار آیتوں میں ہی کئی ٹھوکریں کھائی ہیں کوئی حق نہیں رکھتی کہ اسے اس دوسرے بیان پر جو عقلاً بھی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے ترجیح دی جائے.وَ قَالَ الَّذِي اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِيْ مَثْوٰىهُ اور مصر (کے باشندوں) میں سے جس (شخص) نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی رہائش کی جگہ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا١ؕ وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا با عزت بناامید ہے کہ یہ (لڑکا) ہمارے لئے نفع رساں (ثابت) ہو گا یا ہم اسے (اپنا) بیٹا (ہی)بنا لیں گے اور اس لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ١ٞ وَ لِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ١ؕ طرح سے ہم نے یوسف کواس ملک میں (قدر و)منزلت بخشی اور (ہم نے اسے یہ عزت کا مقام) اس لئے( بھی دیا) وَ اللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۰۰۲۲ تاکہ ہم( اپنی )باتوں کی اصل ؎ حقیقت کاعلم اسےدیں.اور اللہ (تعالیٰ) اپنی بات (کو پورا کرنے) پر( کامل) اقتدار رکھتا ہے لیکن اکثرلوگ (اس حقیقت کو) جانتےنہیں.حلّ لُغَات.مَثْوٰی.مَثْوٰی ثَوَاءٌ میں سے مصدر میمی یا اسم ظرف ہے جس کے معنے ہیں اَلْاِقَامَۃُ مَعَ الْاِسْتَقْرَارِ.کسی جگہ رہائش اختیار کرنا ٹھہرنا.(مفردات) اَلْمَثْوٰی.اَلْمَنْزِلُ.اترنے اور ٹھہرنے کی جگہ (اقرب) مَکَّنْتُہٗ وَمَکَّنْتُ لَہٗ.فَتَمَکَّنَ.وَمَکِیْنٌ.اَیْ مُتَمَکِّنٌ ذُوْقَدْرٍ وَمَنْزِلَۃٍ.یعنی مَکَّنَہٗ اور مَکّنَ لَہٗ کے ؎ اصل مِنْ کا ترجمہ کیا گیا ہے جو حروف زائدہ میں سے ہے اور تاکید کے طور پر آیا ہے.
Page 421
کے یہ معنے ہیں کہ اسے قدرومنزلت بخشی اور مکین صاحب عزت انسان کو کہتے ہیں.(مفردات) مَکَنَ فَلَانٌ عِنْدَالسُّلْطَانِ مَکَانۃً: عَظُمَ عِنْدَہٗ وَارْتَفَعَ وَصَارَ ذَامَنْزِلَۃٍ (یعنی مَکّن کے مجرد) مَکَنَ کے معنے ہیں اس نے قدرومنزلت پائی.(اقرب) تَأْوِیْلُ اَلتَّأْوِیْلُ مِنَ الْاَوْلِ بمعنے اَلرُّجُوْعُ اِلَی الْاَصْلِ تَأْوِیْلٌ کا لفظ اَوْلٌ میں سے باب تفعیل کا مصدر ہے جس کے معنے ہیں کسی چیز کا اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا.وَذٰلِکَ ھُوَرَدُّالشَّیْءَ اِلَی الْغَایَۃِ الْمُرَادَۃِ مِنْہُ.عِلْمًا کَانَ اَوْفِعْلًا.اور تاویل کے معنے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقصود اور غایت کی طرف لوٹانا خواہ اس کا تعلق ذہن اور دماغ سے ہو یا دیگر اعضاء سے.(مفردات) اَلتَّاوِیْلُ :اَلْعَاقِبَۃُ.انجام.بَیَانُ اَحَدِ مُحْتَمِلَاتِ اللَّفْظِ کسی لفظ کے احتمالی معانی میں سے کسی ایک معنے اور مراد کی تعیین کرنا.اَوَّلَ الشَّیْءَ اِلَیْہِ.رَجَّعَہٗ وَمِنْہُ اَوَّلَ اللہُ عَلَیْکَ ضَالَّتَکَ اَیْ رَدَّعَلَیْکَ ضَالَّتَکَ.اَوَّلَ کے معنے ہیں کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر واپس لایا.چنانچہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہوجائے تو اسے دعاء کے طورپر کہا جاتا ہے اَوَّلَ اللہُ عَلَیْکَ ضَالَّتَکَ.اللہ تعالیٰ تیری گم شدہ چیز تیرے پاس واپس لائے.وَالْکَلَامَ دَبَّــرَہٗ وَقَدَّرَہٗ وَفَسَّرَہٗ اور جب اس کا مفعول کوئی کلام ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس میں تدبر کرکے اس کی اصل مراد کو ظاہر کیا.والرُّؤْیَا عَبَّرَھَا اور جب اس کا مفعول رؤیا ہو تو اس کے معنے تعبیر کرنے کے ہوتے ہیں.(اقرب) تفسیر.مصر میں یوسفؑ کو شاہی باڈی گارڈ نے خریدا تھا جب قافلہ مصر میں پہنچا تو اس نے یوسفؑ کو اچھی قیمت پر فروخت کیا.اور جس شخص نے انہیں خریدا اس کا نام یہودی کتب سے فوطی فار معلوم ہوتا ہے.یہ شخص شاہی گارڈ کا افسر تھا.پرانے زمانہ میں باڈی گارڈ کا افسر سب سے بڑا عہدہ دار ہوتا تھا.چنانچہ اسلامی عہدحکومت میں بھی حاجب اور کاتب یعنی باڈی گارڈ کا افسر اور پرائیویٹ سیکرٹری سب سے بڑے عہدے سمجھے جاتے تھے.عباسی خلفاء کے آخر زمانہ میں حاجب کا درجہ کاتب سے بڑا سمجھا جاتا تھا.یوسفؑ کے متعلق اس کا اپنی بیوی کو تاکید کرنا جس وقت اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تو آپ کی شکل اور عادات سے آپ کی شرافت کا قائل ہو گیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے عام خادموں کی طرح نہ سمجھنا بلکہ عزت کے ساتھ رکھنا کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی لیاقت سے ایک دن ہم فائدہ اٹھائیں یا اگر خاص لیاقت کا لڑکا ثابت ہو تو ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنالیں.اس افسر کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہ تھی.وَ لِنُعَلِّمَهٗ کا معطوف علیہ کیا ہے وَ لِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ.یعنی ہم نے یہ اس لئے کیا کہ تا ایک
Page 422
طرف اسے عزت ملے اور دوسری طرف یہ مشکلات میں پڑے اور روحانیت میں ترقی کرے کیونکہ روحانیت کے لئے تکالیف کا آنا بھی ضروری ہے وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ کے آگے لِنُکَرِّمَہُ کا جملہ محذوف ہے.اَیْ لِنُکَرِّمَہُ وَلِنُعَلِّمَہٗ اور اس پر لِنُعَلِّمَہٗ سے پہلی واؤ دلالت کرتی ہے.مشکلات میں پڑنا روحانی علوم کا موجب ہوتا ہے یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس لئے اس افسر کے ہاں جگہ دی کہ تا اس کی عزت بھی ہو اور مشکلات میں پڑ کر روحانی علوم بھی اس پر کھلیں.کیونکہ اس شخص کی بیوی سے جھگڑا پیدا ہوکر حضرت یوسف علیہ السلام نے خاص مجاہدات میں سے گزرنا تھا.وَ لَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّ عِلْمًا١ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي اور جب وہ اپنی قوت (اور مضبوطی کی عمر )کو پہنچا تو ہم نے اسے فیصلہ (کرنے کا منصب )اور( خاص) علم بخشا.الْمُحْسِنِيْنَ۰۰۲۳ اور (حقیقی )نیکوکاروں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں.حلّ لُغَات.اَشُدَّ بَلَغَ فُلَانٌ اَشُدَّہُ اَیْ قُوّتَہُ وَھُوَمَابَیْنَ ثَمَانِیَ عَشْرَۃَ اٰلِی ثَلَاثِیْنَ سَنَۃً یعنی اَشُدَّ کے معنے قوۃ کے اور اس عمر کے ہوتے ہیں جس میں انسان پورے زور پر ہوتا ہے.وَالْمَشْہُورُ انَّ ذٰلِکَ بِمَعْنَی الْاِدْرَاکِ وَالْبُلُوْغِ اور زیادہ مشہور یہ ہے کہ اس کے معنے بلوغت کے ہوتے ہیں.(اقرب) تفسیر.یہ مطلب نہیں کہ جوان ہوتے ہی نبوت کے مقام پر پہنچ گئے.قرآن کریم کا طرز ہے کہ بعض دفعہ درمیانی واقعات کو چھوڑ کر انجام کو لے لیتا ہے.وَ رَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَ غَلَّقَتِ اور جس (عورت) کے گھر میں وہ( رہتا) تھا اس نےاس سے اس کی مرضی کے خلاف (ایک) فعل کروانا چاہا.اور الْاَبْوَابَ وَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ١ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّيْۤ (اس مکان کے )تمام دروازے بند کر دئیے اور کہا (میری طرف) آ جا.اس نے کہا (میں ایسا کرنے سے) اللہ کی
Page 423
اَحْسَنَ مَثْوَايَ١ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ۰۰۲۴ پناہ (چاہتاہوں) وہ یقیناً میرا رب ہے اس نے (ہی )میری رہائش کی جگہ اچھی بنائی ہے بات یہ (ہی) ہے کہ ظالم کامیاب نہیںہوا کرتے.حل لغات.راود رَاوَدَہُ شَاءَ ہٗ اسے چاہا.اس کا خواہاں ہوا.وَعَنْ نَفْسِہٖ وَعَلَیْہَا خَادَعَہٗ.اسے دھوکہ دے کر اس پر قابو پانے کی کوشش کی.وَفِی الْقُرْاٰنِ وَرَاوَدَتْہُ الَّتِی ھُوَفِیْ بَیْتِہَا عَنْ نَّفْسِہٖ.اَیْ طَلَبَتْ مِنْہُ الْمُنْکَرَ اور قرآن کریم کی آیت میں اس کے یہ معنے ہیں کہ اس سے بدی کروانی چاہی اور اس سے بدی کے ارتکاب کی طالب بنی.(اقرب) وَالْمُرَاوَدَۃُ اَنْ تُنَازِعَ غَیْرَکَ فِی الْاِرَادَۃِ فَتُرِیْدُ غَیْرَمَا یُرِیْدُ اَوْتَرُوْدَ غَیْرَ مَایَرُوْدُ.مُرَاوَدَۃٌ.(رَاوَدَ کی مصدر) کے معنے یہ ہیں کہ جو بات ایک شخص کرنا چاہتا ہو اس کے خلاف اس سے چاہنا اور اس سے کروانے کی کوشش کرنا.وَرَاوَدَتْ فُلَانًا عَنْ کَذَا اور اس کا صلہ عن آتا ہے.قَالَ تُرَاوِدُ فَتَاھَا عَنْ نَفْسِہٖ اَیْ تَصْرِفُہٗ عَنْ رَّایِہٖ.جیسا کہ اس آیت میں تُرَاوِدُ کا لفظ ہے جس کے معنے ہیں وہ اسے اس کی رائے اور اس کی مرضی سے ہٹانا اور اس کے خلاف اس سے کروانا چاہتی ہے.(مفردات) ھَیْتَ ھَیْتَ لَکَ اَیْ ھَلُمَّ لَکَ وَتَعَالَ.آجا (اقرب) تَھَیَّأتُ لَکَ.میں تیرے لئے تیار اور آمادہ ہوں.(مفردات) تفسیر.حضرت یوسفؑ اس عورت کے فریب میں نہیں آئے اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے فریب میں نہیں آئے.پس بعض مفسرین کا یہ قول کہ وہ اس کے فریب میں آنے لگے تھے.درست نہیں.اِنَّهٗ رَبِّيْۤ سے مراداس عورت کا خاوند نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے رَبِّيْۤ سے مراد اس جگہ اللہ تعالیٰ ہی ہے.جن لوگوں نے اس کی تفسیر حاجب کی ہے درست نہیں.بے شک حاجب نے ان کو عزت کی جگہ دی تھی مگر اس تک پہنچنا اور اس کے دل میں اس خیال کا پیدا ہونا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے انسان کے متعلق یہ گمان بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ انسانی احسانات کو بنائیں گے نہ کہ الٰہی فضلوں کو جو کچھ انہیں ملا تھا اللہ تعالیٰ کی پیشگوئیوں کے ماتحت ملا تھا.پس اسی کو وہ اپنے تقویٰ کا موجب قرار دیتے ہیں اور گناہ میں اس کے احسانات کی ناشکری محسوس کرتے ہیں.
Page 424
وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ١ۚ وَ هَمَّ بِهَا لَوْ لَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ١ؕ اور اس( عورت) نے اس کے متعلق (اپنا) ارادہ پختہ کر لیا اور اس نے اس کے متعلق (اپنا)ا رادہ پختہ کر لیا (اور) اگر كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَ الْفَحْشَآءَ١ؕ اِنَّهٗ مِنْ اس نے اپنے رب کا روشن نشان نہ دیکھا ہوتا (تو وہ ایسا عزم نہ کر سکتا) اسی طرح پر (ہوا) تاکہ ہم اس سے(ہر ایک) عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ۰۰۲۵ بدی اور بے حیائی (کی بات) کو دور کر دیں (اور)وہ یقیناً ہمارے برگزیدہ (اور پاک کئے ہوئے )بندوں میں سے تھا.حلّ لُغات.ھَمَّ ھَمَّ بِالشَّیْءِ نَوَاہُ وَاَرَادَہٗ وَعَزَمَ عَلَیْہِ وقَصَدَہٗ وَلَمْ یَفْعَلْہُ.پختہ ارادہ اور عزم کر لیا مگر عمل میں نہ لایا.(اقرب) اَخْلَصَ اَخْلَصَ الشَّیْءَ.اِخْتَارَہٗ وَاَخْلَصَہُ اللہُ جَعَلَہٗ مُخْتَارًا خَالِصًا من الدَّنَسِ.اَخْلَصَ کے معنے ہیں اسے چن لیا.اللہ تعالیٰ نے اسے برگزیدہ اور ہر ایک میل سے پاک کیا.(اقرب) تفسیر.هَمَّ بِهٖ سے کیا مراد ہے جیسا کہ حل لغات میں لکھا گیا ہے ھَمَّ بِہٖ کے معنے مضبوط ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں.گو ساتھ ہی یہ اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا.خواہ اس وجہ سے کہ حالات بدل گئے خواہ اس سبب سے کہ روکیں پڑ گئیں.اس آیت میں بتایا ہے کہ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ایک ارادہ کیا لیکن وہ اسے پورا نہ کرسکی.اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے متعلق ایک ارادہ کیا لیکن وہ بھی اس ارادہ کو پورا نہ کرسکے.بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ دونوں نے آپس میں بدی کا ارادہ کیا(درمنثور زیر آیت ھذا الجزءالرابع صفحہ ۱۳) لیکن یہ درست نہیں کیونکہ اس کی نفی پہلی آیت میں ہوچکی ہے.وہاں اللہ تعالیٰ فرماچکا ہے کہ یوسف کو عزیز کی بیوی نے اس کے دلی خیالات کے خلاف پھسلانا چاہا لیکن اس پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کام کے بدانجام سے اس عورت کو بھی ڈرایا.پس اس آیت کی موجودگی میں ھَمَّ بِہٖ کے یہ معنے کسی طرح نہیں کئے جاسکتے کہ یوسفؑ نے اس عورت سے کسی بری بات کا ارادہ کیا.
Page 425
اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کی حالت کے مطابق اس کی طرف ارادہ منسوب کیا جاسکتا ہے.دونوں کی اندرونی حالت کو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے.عورت کی اندرونی حالت یہ بتائی ہے کہ وہ بدی کا ارادہ رکھتی تھی اور یوسف علیہ السلام کی حالت یہ بتائی ہے کہ وہ اسے ظلم کے بدانجام سے ڈراتے تھے.پس اس جگہ دونوں کے ارادوں سے یہی مراد لی جاسکتی ہے کہ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدی کی راہ پر لگانا چاہا اور حضرت یوسف نے اسے نیکی کی راہ پر لگانا چاہا.مگر دونوں اپنے مقصد کو پورا نہ کرسکے نہ یوسف علیہ السلام نے عزیز کی بیوی کی بات مانی اور نہ اس نے یوسف علیہ السلام کی بات مانی.لَوْ لَاۤ اَنْ رَّاٰ الگ جملہ ہے باقی رہا اللہ تعالیٰ کا قول لَوْ لَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ سو یہ ھَمَّ بِھَا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الگ قول ہےاور اس کی جزاء محذوف ہے جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد جگہ جزا محذوف کر دی گئی ہے.جیسے لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ وَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ (النور:۱۱ ) میں اور لَوْ لَاۤ اَنْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَيَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَوْ لَاۤ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰيٰتِكَ وَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (القصص :۴۸) میں محذوف ہے اور اس حصہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے براہین نہ دیکھے ہوئے ہوتے تب ہوسکتا تھا کہ وہ اس ارادہ کے سوا کوئی اور ارادہ کرتے مثلاً اسے نیکی کی طرف نہ بلاتے خاموش ہی رہتے لیکن جبکہ وہ براہین دیکھ چکے تھے تو پھر اس کے سوا اور وہ کرہی کیا سکتے تھے.ہاں یہ آگے اس عورت کی بدقسمتی تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور ظلم پر مصر رہی.برہان سے مراد بُرْھَان کے متعلق بھی مفسرین میں اختلاف ہے.جن لوگوں نے اس آیت کے یہ معنے کئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدی کا ارادہ کیا تھا وہ اس کے یہ معنے کرتے ہیں کہ عزیز کی بیوی اپنے بت پر پردہ ڈالنے لگی تھی کہ اس سے مجھے شرم آتی ہے.اس پر یوسف علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے کہا کہ پھر میں کیوں نہ اپنے خدا سے شرماؤں جو دیکھتا اور جانتا ہے(درمنثور زیر آیت ھذا).بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے چھت پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً (گویا قرآن کریم اس وقت نازل ہوچکا تھا) بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہتھیلی دیکھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ.بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دیکھی کہ وہ انگلیاں دانتوں میں دبا رہے تھے(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھٰذا ) مگر میں لکھ چکا ہوں کہ یہ معنے ہی غلط ہیں.بُرْھَان سے مراد وہی آیات اور نشانات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے ظاہر ہوچکے تھے.مثلاً ان کی رؤیا آئندہ روحانی ترقیات کے متعلق پھر کنوئیں میں ڈالتے وقت کا الہام کہ اللہ تعالیٰ
Page 426
تجھے اس بلا سے بچا کر ترقی دے گا اور ایک دن تیرے بھائی تیرے سامنے پیش ہوں گے اور اس میں کیا شک ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ایسے عظیم الشان کام کے لئے تیار کررہا ہو اسے اللہ تعالیٰ ایک مشرکہ کے سامنے شرمندہ نہیں کرسکتا تھا.کَذَالِکَ کا مُشَارٌّ اِلَیْہ اور صَرْفُ السُّوْءِ سے مراد كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ سے یہ مراد ہے کہ ہم نے اسے براہین دکھائے ہی اس لئے تھے کہ اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں.پس جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس غرض سے یہ نشانات دکھائے تھے تو کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے منشاء کے خلاف نتیجہ نکلتا.دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ یہ واقعہ اس لئے ظاہر ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ یوسفؑ کو اس عورت کی بدصحبت سے نجات دلائے.یہ ایک حقیقت ہے کہ بد لوگوں میں رہ کر انسان کے خیالات اور اس کے دماغ پر بُرا اثر پڑتا ہے اگر اس طرح عزیز کی بیوی اپنے بدارادہ کا اظہار نہ کرتی تو اس کی اور اس کی ہم جولیوں کی صحبت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہنا پڑتا.جن کے اخلاق قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نہایت گندے تھے.پس اللہ تعالیٰ نے پسند نہ فرمایا کہ آپ ان کی صحبت میں رہیں اور اس کے بدارادوں کو پوری طرح اور جلد اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرادیا اور اس طرح انہیں ان سے جدا کرکے قیدخانہ میں بھجوا دیا جہاں علیحدگی میں عبادت الٰہی کا خاص موقع ان کو مل گیا.گیارھویں مشابہت آنحضرتؐ کوبھی پھسلانے کی کوششیں کی گئیں اس بارہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہت ہے.آپؐ کے دشمنوں نے بھی آپ کو لالچ دے کر دین سے پھرانا چاہا تھا.چنانچہ تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کا ایک وفد آیا اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نے یہ دعویٰ روپیہ کے لئے کیا ہے تو ہم اس قدر روپیہ جمع کردیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں.اور اگر عزت کے لئے کیا ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنالیتے ہیں.اور اگر عورت کی آپ کو خواہش ہو تو سب سے حسین عورت آپ کی خدمت میں پیش کردیتے ہیں.مگر آپ یہ وعظ چھوڑ دیں.اس پر آپؐ نے جواب دیا کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لاکھڑا کرو تب بھی میں تمہاری بات نہیں مان سکتا.قرآن کریم میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے اور اس آیت سے ملتے جلتے الفاظ میں ہے.فرماتا ہے وَ اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ۠ عَنِ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ١ۖۗ وَ اِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا.وَ لَوْ لَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا (بنی اسرائیل :۷۴) اور قریب تھا کہ یہ لوگ تجھے ابتلاؤں میں ڈال دیں بوجہ اس کلام کے جو ہم نے تیری طرف بطور وحی نازل کیا ہے تاکہ تو اس کلام کے سوا کوئی اور کلام اپنے پاس سے بناکر پیش کردے اس صورت میں یہ لوگ ضرور
Page 427
تجھے اپنا دوست بنالیتے.اور اگر ہم تیرے دل کو کلام الٰہی سے مضبوط نہ کردیتے تو اس صورت میں قریب ہوتا کہ تو ان کی طرف کسی قدر جھک جاتا.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرتے تھے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوسکے کیونکہ الہام الٰہی نے آپؐ کا دل مضبوط کر چھوڑا تھا.آنحضرت ؐپر بھی بحوالہ قرآن کریم پھسلنے کا الزام لگایا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے مزید مشابہت یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگوں نے حضرت یوسفؑ کے متعلق قرآن کریم کی آیات کے یہ معنے کئے ہیں کہ وہ کچھ جھک گئے تھے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ معنے کئے ہیں کہ آپؐ بھی کچھ جھک گئے تھے حالانکہ قرآن کریم دونوں جگہ اس کے خلاف مضمون بیان کرتا ہے.وَ اسْتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّ اَلْفَيَا سَيِّدَهَا اور وہ (دونوں) دروازہ کی طرف دوڑے اور اس (کشمکش میں اس عورت) نے اس کے کرتے کو پیچھے سے پھاڑ دیا لَدَا الْبَابِ١ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّاۤ اور(جب وہ دروازہ تک پہنچے تو) انہوں نے اس (عورت) کے خاوند کو دروازہ کے پاس (کھڑا) پایا (جس اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۰۰۲۶ پر) اس (عورت)نے (اپنے خاوند سے )کہا جو( شخص) آپ کے اہل سے بدی (کرنا) چاہے اس کی سزا سواء اس کے (کوئی) نہیں (ہونی چاہیے )کہ اسے قیدکردیا جائے.یا (اسے) کوئی اور دردناک عذاب (دیا جائے).حلّ لُغَات.اِسْتِبَاقٌ اِسْتَبَقَاتَسَابَقَا یعنی اِسْتَبَقَا کے وہی معنے ہیں جو تَسَابَقَا کے ہیں.تَسَابَقَا.سَبَقَ اَحَدُھُمَا الاٰخَرَ اَوْاَرَادَ اَنْ یَسْبِقَہٗ.اور تَسَابَقَا کے معنے ہیں وہ دونوں مقابلہ کے طور پر دوڑے جن میں سے ایک آگے نکل گیا.یا یہ کہ ہر ایک نے دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا.الصِّرَاطَ جَاوَزَاہُ وَتَرَکَاہُ حَتّٰی ضَلَّا.اور جب اس کے بعد مفعول مذکور ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں وہ اس سے آگے نکل گئے وَ اَمَّاقَوْلُہٗ وَاسْتَبَقا الْبَابَ فَبِتَقْدِیْرِ الْجَارِ.اَیْ تَسَابَقَا اِلَیْہِ اَوْ عَلٰی تَضْمِیْنِ الْفِعْلِ مَعْنَی الاِبْتِدَارِ اَیْ اِبْتَدَرَا الْبَابَ.لیکن اس آیت میں یہ لفظ ان معنوں میں نہیں آیا بلکہ یا تو اس کے مفعول سے حرفِ الیٰ
Page 428
محذوف ہے اور یا اِسْتَبَقَا کے لفظ میں اِبْتَدَرَا کے معنے ملحوظ ہیں اس لئے اس جگہ معنے یہ ہیں کہ وہ دونوں دروازہ کی طرف دوڑے نہ یہ کہ دروازہ سے آگے نکل گئے.(اقرب) قَدَّ قَدَّ الشَّیْءَ.قَطَعَہٗ مُسْتَأْصِلًا.اسے بالکل پھاڑ دیا.اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا.وَقِیْلَ مُسْتَطِیْلًا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنے لمبی طرف سے پھاڑ کر پارہ پارہ کرنے کے ہیں.وَقِیْلَ شَقَّہٗ مُسْتَطِیْلًا اور بعض نے اس کے یہ معنے بیان کئے ہیں کہ اسے لمبائی کی طرف سے چیر دیا.(اقرب) تفسیر.حضرت یوسف ؑ نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو انہوں نے اس خیال سے کہ اب زیادہ ٹھہرنا بدنامی کا موجب ہوگا دوڑنا چاہا لیکن عزیز کی بیوی نے اس سے ان کو روکا اور ان کا کُرتا پکڑ کر کھینچا جو طول میں پھٹ گیا.اتفاقاً اسی وقت عزیز مصر بھی آ گیا اور اس کی بیوی نے اپنے گناہ کو اس طرح چھپایا کہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگادیا اور فوراً سزا بھی خود ہی تجویز کردی کہ اسے قید کردینا چاہیے.عزیز کی بیوی کا بھاگنے سے کیا مقصد تھا الفاظ آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا منشاء تو یہ تھا کہ وہ دروازہ کھول کر بھاگ جائیں اور عزیز کی بیوی کا منشاء یہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے سے روکے اسی وجہ سے اِسْتَبَقَا کا لفظ استعمال کیا ہے ورنہ اگر اس کا منشاء باہر نکلنے کا ہوتا تو وہ کرتہ نہ کھینچتی.کرتہ اس نے اس لئے کھینچا کہ ان کو دھکا دے کرپیچھے کردے اور خود دروازہ پر جاکھڑی ہو مگر باوجود اس کے وہ کامیاب نہ ہوسکی.حضرت یوسف اپنا کرتہ وہیں چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے بائبل کو اس جگہ بھی قرآن کریم سے اختلاف ہے.اس میں لکھا ہے کہ حضرت یوسفؑ اپنا پیراہن عزیز کی بیوی کے پاس چھوڑ کر بھاگ گئے(پیدائش باب ۳۹ آیت ۱۲) مگر جب ہم اس امر کو مدنظر رکھیں کہ عبرانیوں میں عام طور پر ایک کرتہ ہی پہننے کا رواج تھا تو اس کے یہ معنی بنتے ہیں کہ وہ ننگے بھاگے جو ایک نہایت معیوب امر ہے اور اس کی امید حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں کی جاسکتی.پس قرآن کریم کا بیان عقلاً بھی زیادہ قابل تسلیم ہے کہ ان کا کرتہ پھٹ گیا تھا وہ اسے پھینک کر نہیں بھاگے.
Page 429
قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اس نے (یعنی یوسف نے) کہا (نہیں بلکہ) اس نے مجھ سے میری مرضی کے خلاف (ایک) فعل کروانا چاہا تھا.اور اَهْلِهَا١ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ اس (عورت ہی)کے کنبہ میں سے ایک گواہ نے گواہی دی (کہ اس عورت کے کپڑے صحیح سلامت ہیں اور اس آدمی مِنَ الْكٰذِبِيْنَ۰۰۲۷ کا کرتہ تازہ پھٹا ہوا ہے پس) اگر اس کا کُرتہ آگے سے پھاڑاگیاہےتو اس( عورت) نے سچ کہا ہے اور وہ( آدمی) یقیناً جھوٹا ہے.حلّ لُغَات.شَھِدَ شَھِدَ الْمَجْلِسَ شُہُوْدًا حَضَرَہٗ.اس میں حاضر اور موجود ہوا.اِطَّلَعَ عَلَیْہِ اس سے آگاہ ہوا.عَایَنَہٗ.اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا.الْـجُمْعَۃَ اَدْرَکَہَا.نمازجمعہ میں وقت پر پہنچ کر شامل ہو گیا.عَلٰی کَذَا.اَخْبَرَبِہِ خُبُرًا قَاطِعًا.اس کے متعلق صحیح صحیح خبر یا اطلاع دی.عِنْدَ الْحَاکِمِ لِفُلَانٍ عَلٰی فُلَانٍ بِکَذَا شَھَادَۃً اَدَّیٰ مَاعِنْدَہٗ مِنَ الشَّہَادَۃِ.شہادت دی(اقرب) وَ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۰۰۲۸ اور اگر اس( شخص) کا کرتہ پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس( عورت) نے جھوٹ بولا ہے اور وہ یقیناً سچا ہے.حلّ لُغَات.صِدْقٌ الصِّدْقُ بِالْکَسْرِ نَقِیْضُ الْکَذِبِ.خبر کا غلط نہ ہونا بلکہ واقع کے مطابق ہونا.یا کہنے والے کا واقع کے مطابق بات کہنا اور خلاف واقع نہ کہنا.ھُوَالذِیْ یَکُوْنُ مَافِی الذِّھْنِ مِنْہُ مُطَابِقًا لِمَا فِی الْخَارِجِ.وہ بات جس میں انسان کا علم واقعات کے مطابق ہو.(اقرب) اَلصِّدْقُ مُطَا بَقَۃُ الْقَوْلِ الضَّمِیْرَ وَالْمُخْبَرَعَنْہُ مَعًا صدق اسے کہتے ہیں کہ جو بات کہی جائے وہ متکلم کے ضمیر کے مطابق ہو اور نفس الامر کے بھی.وَمَتَی انْخَرَمَ شَرْطٌ مِنْ ذٰلِکَ لَمْ یَکُنْ صِدقًا تَامًّا اور جب دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط یا دونوں شرطیں مفقود ہوں تو صدق نہیں رہے گا.بَلْ اِمَّا اَنْ لَّا یُوْصَفَ بِالصِّدْقِ.
Page 430
وَاِمَّا اَنْ یُّوْصَفَ تَارَۃً بِالصِّدْقِ وَتَارَۃً بِالْکَذِبِ عَلٰی نَظَرَیْنِ مُخْتَلِفَیْنِ بلکہ یا تو اسے مطلقاً غیر صدق کہا جائے گا اور یا پھر کبھی اس کا نام صدق رکھا جائے گا کیونکہ اس میں صدق کی ایک علامت موجود ہے اور کبھی اسے کذب کہا جائے گا.کیونکہ کذب کی بھی ایک علامت اس میں موجود ہے.(مفردات) صدق کے معنوں کے متعلق اقرب الموارد اور مفردات راغب کے بیانات میں جو اختلاف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صدق اور کذب کی حقیقت اور ماہیت اور اہل زبان کے محاورات اور استعمال کی رو سے ان کے مفہوم کے متعلق محققین ارباب لغت میں اختلاف ہے.اکثر محققین کا (جیسا کہ علّامہ تفتازانی وغیرہ نے بیان کیا ہے) وہ خیال ہے جسے اقرب الموارد میں مقدم کیا گیا ہے.اور بعض کے نزدیک متکلم کے اعتقاد اور ضمیر پر اس کا مدار اور انحصار ہے.پس جو بات متکلم کے ضمیر کے مطابق ہو وہ صدق ہو گی خواہ واقع میں صحیح ہو یا غلط اور جو بات متکلم کے نزدیک خلاف واقع ہو اور اس نے اسے غلط سمجھتے ہوئے کہا ہو وہ کذب متصور ہوگی خواہ فی الواقع صحیح ہی کیوں نہ ہو اور بعض محققین کے نزدیک صادق وہ خبر ہے جو ضمیر اور واقع ہر دو کے مطابق ہو.اور کاذب وہ ہے جو ہر دو کے خلاف ہو.اور جو بات واقع اور ضمیر متکلم میں سے ایک کے مطابق اور ایک کے خلاف ہو وہ ان کے نزدیک حقیقی معنوں میں نہ صادق ہوگی نہ کاذب.بلکہ ان ہر دو کے درمیان درمیان اور ایک تیسری چیز ہوگی.جسے مجازی طور پر صادق بھی کہا جاسکتا ہے اور کاذب بھی.جیسا کہ جاحظ کا خیال ہے اور امام راغب نے مفردات میں اسی کو اختیار کیا ہے.تفسیر.حضرت یوسفؑ کا حقیقت حال کے اظہار میں پہل نہ کرنا خدا تعالیٰ کے برگزیدوں کی یہی شان ہوتی ہے.باوجود اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مظلوم تھے آپ پہلے نہیں بولے اور عزیز کی بیوی کے فعل پر پردہ ہی ڈالا لیکن جب اس نے الزام لگایا تو پھر مجبوراً حقیقت حال کو ظاہر کیا کہ میرے دل میں تو کبھی خیال نہیں آیا ہاں یہ میرے ارادہ کے خلاف کام پر مجبور کرتی رہی ہے.حضرت یوسفؑ کی بریّت کا سامان اللہ تعالیٰ نے خود ہی یوسف علیہ السلام کے لئے سامان پیدا کردیئے اور ایک شخص ان کے حق میں گواہی دینے والا کھڑا ہو گیا.جس نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ اگر یوسف بدارادہ کرتا تو اس کا کرتہ آگے کی طرف سے پھٹنے کا زیادہ امکان تھا لیکن پیچھے سے کرتے کا پھٹنا تو صاف بتاتا ہے کہ وہ بے چارہ بھاگ رہا تھا اور یہ عورت اسے روک رہی تھی.عزیز کی بیوی کے خوف سے شاہد کا ادائے شہادت میں ابہام رکھنا چونکہ اس سے پہلے کرتے کے پھٹنے کا کوئی ذکر نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گواہ نے خود ہی کرتہ پھٹا ہوا دیکھا ہے اور جب اس نے خود دیکھا تھا
Page 431
تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا.پس ظاہر ہے کہ اس شخص نے عزیز کی بیوی کے لحاظ سے صاف طور پر یہ نہیں کہا کہ اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے پس یہ مجرم نہیں بلکہ اس طرح بات کی ہے کہ گویا ایک قاعدہ بتارہا ہے تاکہ عزیز کی بیوی اس پر ناراض نہ ہو.عزیز کی بیوی کانام عزیز کی بیوی کا نام مسلمانوں کی کتب میں زلیخا لکھا ہے.بائبل میں اس کا نام نہیں آتا.لیکن یہود کی روایات کی کتاب یعنی طالمود میں اس کا نام زلیخا ہی لکھا ہے(Talmud by H.Palano p.80 Chapter iv).معلوم ہوتا ہے کہ انہی سے مسلمان مفسرین نے نقل کیا ہے.فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ١ؕ اِنَّ پس جب اس (کے خاوند) نے اس کے (یعنی یوسف کے) کُرتے کو دیکھا کہ پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ۰۰۲۹ (اپنی بیوی سے )کہا یہ (جھگڑا) یقیناً تمہاری چالاکی سے (پیدا ہوا) ہے تم عورتوں کی چالاکی یقیناً بہت بڑی (ہوتی) ہے.تفسیر.یہ عزیز کا کلام معلوم ہوتا ہے اس شاہد کے توجہ دلانے پر اس نے کرتہ جب پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو حقیقت کو سمجھ گیا اور بیوی سے صاف کہہ دیا کہ یہ تیری چالاکی ہے.عورتیں گہری تدبیریں نسبتاً زیادہ کیوں کرتی ہیں اس آیت سے بعض لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ عورتیں خاص طور پر مکار ہوتی ہیں.اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتیں بوجہ ان مظالم کے جو ان پر کئے جاتے ہیں گہری تدابیر کی زیادہ عادی ہوتی ہیں اور بات کا پھرانا ان کا خاص فن ہوگیا ہے مگر اس کا سبب ان کے حقوق کااتلاف ہے جن قوموں یا گھرانوں میں عورتوں کے حقوق پورے طور پر ادا ہوتے ہوں ان کی عورتیں ایسی نہیں ہوتیں اس کے برعکس جو اقوام ظالموں کے تصرف میں ہوتی ہیں ان کے مرد بھی اس مزاج کے ہوجاتے ہیں.پس یہ مادہ عورت سے مخصوص نہیں بلکہ ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے اور مرد اور عورت دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں.یہ خدائی فیصلہ نہیں بلکہ عزیز کا قول ہے علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ عزیز کا قول ہے اور اس کا قول ہم پر حجت نہیں ہے اس نے غصہ کی حالت میں یہ بات کہہ دی ہے کہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں اور جو لوگ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتے وہ ہمیشہ ایسی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں.
Page 432
یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے عورتیں مردوں کو کہتی رہتی ہیں کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں اور مرد عورتوں کو کہتے رہتے ہیں کہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں اس کو ایک قاعدہ اور کلی صداقت قرار دینا محض نادانی اور ناواقفیت کی علامت ہے.کہنے والے کی مراد اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ مخاطب یا اس کے ساتھی فعل زیربحث میں غلطی پر ہیں اور ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ تمام افراد ایسے ہیں اور اگر یہ مراد ہو تو یقیناً وہ غلطی پر سمجھا جائے گا جس جنس نے مریم ، ؑ خدیجہؓ ،عائشہؓ اور ایسی ہی اور بہت سی عورتیں پیدا کی ہیں اس کی نسبت ایک قاعدہ کے طور پر ایسا کلام کہنا خود اپنی پردہ دری کرنا ہے.يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا١ٚ وَ اسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ١ۖۚ اِنَّكِ یوسف! تو اس (عورت کی شرارت) سے چشم پوشی کرا ور( اے عورت) اپنے قصور کی بخشش طلب کر.كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَؒ۰۰۳۰ یقیناً تو ظالموں میں سے ہے.حلّ لُغَات.اَعْرَضَ اَعْرَضَ عَنْہُ اَضْرَبَ وَصَدَّ.اس سے رخ ہٹا لیا.اور اس کی طرف سے ہٹ کر دوسری طرف توجہ کرلی وَحَقِیْقَتُہٗ جَعَلُ الْہَمْزَۃِ لِلْصَّیْرُوْرَۃِ اَیْ اَخَذَتُ عُرْضًا اَیْ جَانِبًا غَیْرَالْجَانِبِ الَّذِیْ ھُوَ فِیْہِ.اور اس کے یہ معنے باب افعال کی خاصیّت صیرورت کے ماتحت پیدا ہوئے ہیں.یعنی جس طرف دوسرا شخص ہے اسے چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کرلیا اور دوسری جانب کو اختیار کر لیا.(اقرب) پس اَعْرِضْ عَنْ ھٰذَا کے یہ معنے ہوئے کہ اس بات سے چشم پوشی کر اور اسے خاطر میں نہ لا.تفسیر.عزیز نے اپنی بیوی کی بات پر اعتبار نہیں کیا تھا یہ بھی عزیز کا کلام ہے.وہ ایک طرف تو اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو پردہ پوشی کے لئے کہتا ہے.یہاں بھی بائبل اور قرآن کریم میں اختلاف ہے.بائبل کی شہادت کہ عزیز کو حضرت یوسف کی براءت کا یقین تھا بائبل کہتی ہے کہ اس نے بیوی کی بات پر اعتبار کرلیا اور یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار دیا اور اس پر ناراض ہوا(پیدائش باب ۳۹ آیت ۱۹.۲۰).مگر بائبل ہی کے دوسرے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا بیان سچا ہے اور بائبل کا غلط ہے.چنانچہ کتاب پیدائش باب۳۹ میں لکھا ہے.
Page 433
’’اور قیدخانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا اور جو کام وہاں کیا جاتا تھا اس کا مختار وہی تھا.‘‘ (آیت ۲۲) اور بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیدخانہ عزیز فوطیفار کے ہی ماتحت تھا.چنانچہ لکھا ہے کہ’’ فرعون اپنے دو سرداروں پر جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نان پزوں کا داروغہ تھا غصے ہوا اور اس نے انہیں نگہبانی کے لئے جلوداروں کے سردار کے گھر میں اس جگہ جہاں یوسف بند تھا قیدخانہ میں ڈالا.جلوداروں کے سردار یعنی عزیز نے انہیں یوسف کے حوالہ کیا.‘‘ باب۴۰ آیت ۲ تا۴.اب یہ عقل کے خلاف امر ہے کہ فوطیفار تو یوسف علیہ السلام کو اپنی عزت پر حملہ کرنے والا سمجھے اور اس کا نوکر داروغہ اس کو جیل کا افسر مقرر کردے اور یہ امر اور بھی عقل کے خلاف ہے کہ بادشاہ کے خاص قیدی جب عزیز کے سپرد کئے جائیں تو وہ خود انہیں یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں دے دے.پس ان حوالہ جات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عزیز کو حضرت یوسفؑ کی براء ت پر پورا یقین تھا اور قرآن کریم کا بیان صحیح ہے اور بائبل کا غلط.وَ قَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا اور اس شہر کی بعض عورتوں نے (ایک دوسری سے) کہا (کہ) عزیز کی عورت اپنے غلام سے اس کی مرضی کے خلاف عَنْ نَّفْسِهٖ١ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا١ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ (بُرا) فعل کر وانا چاہتی ہے (اور) اس کی محبت نے اس کے دل کی گہرائیوںمیں گھر کر لیاہے.ہم( اس معاملہ میں) مُّبِيْنٍ۰۰۳۱ اسے یقیناً( کھلی) کھلی غلطی پر دیکھتی ہیں.حلّ لُغَات.عَزیْزٌ.اَلْعَزِیْزُ.اَلشَّرِیْفُ.بڑا آدمی.اَلْقَوِیُّ.طاقت والا.اَلْمُکَرَّمُ.معزّز.مِنْ اَسْمَآئِہٖ تَعالٰی وَھُوَ الْمَنِیْعُ الَّذِیْ لَایُنَالُ وَلَا یُغَالَبُ.یہ خدا تعالیٰ کا نام بھی ہے اور اس کے معنی ہیں وہ ذات جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ اس کا کوئی مقابلہ کرسکتا ہے.اَلْمَلِکُ لِغَلَبَتِہٖ عَلٰی اَھْلِ مَمْلِکَتِہٖ.بادشاہ کو بھی عزیز کہتے ہیں کیونکہ اپنی حکومت کے تمام لوگوں پر غلبہ رکھنے والا ہوتا ہے.وَلَقَبُ مَنْ مَلَکَ مِصْرمَعَ
Page 434
الْاِسْکَنْدریَّۃِ.مصر اورا سکندریہ کے حکمران کا لقب.(اقرب) شَغَفَ شَغَفَ شَغْفًا اَصَابَ شَغَافَہٗ اس کے شغاف (یعنی اندرو ن د ل) میں جا پہنچا.شَغِفَہُ حُبُّہٗ شَغَفًا عَلِقَ بِالشَّغَافِ.اس کی محبت اس کے دل کے اندر چلی گئی اور پختہ طور پر پیوستہ ہو گئی.اَلشَّغَافُ غِلَافُ الْقَلْبِ وَقِیْلَ حِجَابُہُ وَقِیْلَ سُوَیْدَاؤُہٗ.شغاف کے معنے ہیں دل کا پردہ یا دل کا حجاب یا دل کا وسطی نقطہ.(اقرب) اَلضَّلَالُ.اَلضَّلَالُ.اَلْہَلَاکُ تباہی.اَلْفَضِیْحَۃُ رسوائی.اَلْبَاطِلُ.غلط بات.ضِدُّ الْھُدٰی.راہ یابی کے خلاف یعنی درست راہ سے دوری(اقرب) اِنَّکَ لَفِیْ ضَلَالِکَ الْقَدِیْمِ وَ اِنَّ اَبَانَا لَفِیْ ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ.اِشَارَۃً اِلَی شَغَفِہِ بِیُوْسُفَ وَ شَوْقِہٖ اِلَیْہِ.وَکَذٰلِکَ قَدْ شَغَفَہَا حُبًّا.اِنَّا لَنَرَاھَا فِیْ ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ یعنی ان آیات میں ضلال سے مراد سخت اور پُرزور محبت و اشتیاق ہے.(مفردات) تفسیر.یہ عزیز بادشاہ نہیں تھا بلکہ بادشاہ کا حاجب تھا عزیز کا ترجمہ عزیز ہی کیا گیاہے.کیونکہ آج کل کی اصطلاح میں عزیز مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں لیکن عورت مصر کے بادشاہ کی نہیں بلکہ اس کے حاجب کی بیوی تھی پس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے وقت میں عزیز کا لفظ سرداران مصر کے متعلق بھی استعمال ہوتا تھا یا پھر عورتوں نے خوشامدانہ طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ بڑے آدمیوں کو ان کے ماتحت بادشاہ وغیرہ کے الفاظ سے یاد کرلیتے ہیں.ان عورتوں کا حضرت یوسفؑ کو بھی ملوث ظاہر کرنا جب یوسف علیہ السلام کو عزیز کی بیوی سے یہ واقعہ پیش آیا تو اس کا چرچا عزیز کے خاندان سے تعلق رکھنے والے گھرانوں میں بھی شروع ہو گیا.بعض عورتیں جو معلوم ہوتا ہے کہ عزیز کی بیوی کی سہیلیاں تھیں جب انہیں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس کا عام تذکرہ کرنا شروع کیا.لیکن عزیز کی بیوی کو مزید بدنام کرنے کے لئے ایسے الفاظ میں تذکرہ شروع کیا جس سے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کوئی کوشش کی تھی اور وہ ناکام رہی بلکہ یوں کہنا شروع کیا کہ گویا وہ فعل جاری ہے اور اس طرح گویا نتیجہ کو مشتبہ کرکے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملوث قرار دیا.شَغَفھا حُبًّا کے معنی قَدْ شَغَفَھَا حُبًّا میں حُبًّا تمیز ہے اور اس کا ترجمہ اسی طرح کریں گے جس طرح طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسًا کا کرتے ہیں یعنی جس طرح وہاں طَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسُہٗ مراد ہوتا ہے اسی طرح یعنی شَغَفَہَا حُبُّہٗ مراد لیا جائے گا اور معنے یہ ہوں گے کہ یوسف کی محبت اس کے دل کے پردوں میں گھس گئی ہے یعنی وہ شدید محبت میں مبتلا ہو گئی ہے کہ اب اسے چنداں بدنامی کا بھی ڈر نہیںرہا.
Page 435
ان عورتوں کی ایک چالاکی گویا وہ ظاہر الفاظ میں اس کی معذوری بیان کرتی ہیں اور اصل میں اس کے عیب کی اشاعت مقصود ہے.فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَ اَعْتَدَتْ اور جب اس نے ان کے (اس) منصوبہ کی خبر سنی تو انہیں( دعوت کا) پیغام بھیجا اور ان کے لئے ایک (خاص) لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّ اٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّ قَالَتِ مسند تیار کی اور (جب وہ آئیںتو) ان میں سے ہر ایک کو (کھانا کھانے کے لئے ایک) ایک چھری دی اور( یوسف اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ١ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ علیہ السلام سے )کہا( کہ) ان کے سامنے آ.پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے (بہت) بڑی شان کا( انسان) وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا١ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ۰۰۳۲ پایا اور( اسے دیکھ کر)اپنے ہاتھ کاٹے اور کہا (کہ یہ شخص محض) اللہ (تعالیٰ) کے لئے (بدی کے ارتکاب سے) ڈرا ہے.یہ بشر (ہے ہی) نہیں یہ( تو) صرف ایک معزز فرشتہ ہے.حلّ لُغَات.سَمِع بِہٖ سَمِعَ بِہٖکے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ بات شہرت پاگئی.اور اس ذریعہ سے اسے بھی پہنچ گئی.چنانچہ اقرب الموارد میں سَمَّعَ کے معنی لکھے ہیں سَمَّعَ بِکَذَا شَیَّعَہٗ اسے شہرت دی.بِالرَّجُلِ اَذَاعَ عَنْہُ عَیْبًا وَنَدَّدَ بِہٖ وَشَھَّرَہٗ وَفَضَحَہٗ.اس کے متعلق کوئی عیب کی بات پھیلائی اور اسے شہرت دے کر اس کو رسوا کیا.پس سَمِعَ بِہِ کے معنے یہ ہوئے کہ اس کے متعلق بات مشہور ہوئی جسے اس نے بھی سنا.اِتَّکَأَ.اِتَّکَأَ جَلَسَ مُتمَکِّنًا.خوب جم کر بیٹھا.یُقَالُ اِتَّکَأَ عَلَی السَّرِیْرِ.چنانچہ تخت پر بیٹھنے کو اِتِّکَاء ہی کہتے ہیں.اَلْقَوْمُ عِنْدَ فُلَانٍ طَعِمُوْا عِنْدَہٗ.انہوں نے اس کے ہاں کھانا کھایا.قَالَ جَمِیْلٌ فَظَلِلْنَا بِنِعْمَۃٍ وَاتَّکَأْنا.اَیْ طَعِمْنَا.چنانچہ جمیل اپنے ایک واقعہ کا ان اوپر کے الفاظ میں ذکر کرتا ہے.یعنی ہم دن بھر عیش و عشرت کرتے رہے اور خوب کھایا پیا.عَلٰی عَصَاہُ تَحمَّلَ وَاعْتَمَدَ عَلَیْہَا.اپنی چھڑی پر ٹیک لگائی اور اپنا بوجھ اس پر ڈالا.قَالَ ابْنُ الْاَثِیْرِ وَالْعَامَّۃُ لَاتَعْرِفُ الْاِتِّکَاءِ اِلَّا الْمَیْلَ فِی الْقُعُوْدِ مُعْتَمِدً اعَلَی اَحَدِ الشِّقَّیْنِ.
Page 436
ابن اثیر کہتا ہے کہ عَامَۃُ النَّاس اِتِّکَاء کا لفظ صرف اس طور پر سہارا لگا کر بیٹھنے کے معنے میں استعمال کرتے ہیں جس میں کسی چیز سے اپنے پہلو کو لگایا جائے.وَھُوَیُسْتَعْمَلُ فِی الْمَعْنَیَیْنِ جَمِیْعًا لیکن درست بات یہ ہے کہ خواہ کسی چیز کا سہارا دیا جائے یا پہلو کو ہر دو صورتوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.یُقَالُ اِتَّکَأَ اِذَا اَسْنَدَ ظَہْرَہُ اَوْجَنْبَہٗ اِلٰی شَیْءٍ مُعْتَمِدًا عَلَیْہِ چنانچہ جب کوئی شخص کسی چیز سے اپنی پیٹھ کو سہارا دے یا اپنے پہلو کو ٹکائے تو ان دونوں صورتوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے وَکُلُّ مَنِ اعْتَمَدَ عَلٰی شَیْءٍ فَقَدْ اِتَّکَأَ عَلَیْہِ اور جس چیز کا بھی سہارا لے کر بیٹھیں اس کے لئے اِتِّکَاء کا لفظ بولا جاسکتا ہے وَالْمُتَّکَأُ مَجْلِسُ یُتَّکُأُ عَلَیْہِ اور مُتَّکَأٌ ایسی بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں جس سے سہارا لیا جائے.(اقرب) سِکِّینٌ.سِکِّیْنٌاسم جنس ہے جس کا واحد سِکِّیْنَۃٌ ہے.السِّکِّینُ آلَۃٌ یُذْبَحُ بِہَا.چھری.اَلسِّکّیْنُۃُ السِّکِّیْنُ وَھِیَ اَخَصُّ مِنْہُ.سِکِّیْنَۃٌ کے معنے ایک چھری کے ہیں.یہ سَکِّیْنٌ سے خاص ہے.کیونکہ یہ صرف واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے.اور سِکِّیْنٌ واحد اور جمع ہر دو کے لئے.اَلطّمَأْنِیْنَۃُ کَالسِّکِّیْنۃِ سِکِّیْنَۃٌ کے معنے اطمینان اور سکینت کے بھی ہیں.(اقرب) خَرَجَ عَلَیْہِ خَرَجَ کا صلہ عَلٰی ہو تو اس کے معنی سامنے آنے کے ہوتے ہیں.جو ہر موقعہ کے مناسب حال الگ الگ صورت پر ہوتے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں خَرَجَ عَلَیْہِ.اَیْ بَرَزَلِقِتَالِہِ.جنگ کرنے کے لئے سامنے آیا.الرَّعِیَّۃُ عَلَی الْوَالِی خَلَعَتْ طَاعَتَہٗ رعیت اپنے حاکم کی اطاعت کا جؤا اتار کر اس کے مقابلہ پر آمادہ ہو گئی.الوَالِی عَلَی السُّلْطَانِ تَمَـرَّدَکسی علاقہ کا والی اپنے بادشاہ سے سرکش ہوکر اس کے مقابل پر کھڑا ہو گیا.(اقرب) پس اُخْرُجْ عَلَیْہِنَّ کے معنے ہوئے ان کے سامنے آ.اَکْبَرَہٗ اَکْبَرَہٗ رَاٰہُ کَبِیْرًا وَعَظُمَ عِنْدَہٗ اس نے اسے بڑا سمجھا اور اس کی عظمت اس کے دل میں قائم ہو گئی.(اقرب) حَاشَحَاشَ مِنْہُ یَحِیْشُ حَیْشًا.فَزِعَ ڈر گیا.ڈر کر دور رہا.(اقرب) حَاشٰی زَیْدًا مِنَ الْقَوْمِ اِسْتَثْنَاہُ.اسے دوسروں سے الگ رکھا.حَاشَا وَیُقَالُ فِیْہَا اَیْضًا حَاشَ وَحَشٰی.قَالَ فِی الْاِیْضَاحِ کَلِمَۃٌ اسْتُعْمِلَتْ لِلْاِسْتِثْنَاءِ فِیْمَـا یُنَزَّہُ فِیْہِ الْمُسْتَثنٰی عَنْ مُشَارَکۃِ الْمُسْتَثْنٰی مِنْہُ فِی حُکْمِہِ.یَعْنِی حَاشَا.حَاشَ.یَا حَشٰی کا لفظ ایسے موقع پر استثناء کے لئے استعمال ہوتا ہے جہاں اس کے مدخول کا شرف ظاہر کرنا اور اس شرف میں اسے باقی سب سے ممتاز اور الگ بتانا مقصود ہو.(اقرب) پس اگر حَاشَ کو حَیْشٌ کی
Page 437
ماضی کا صیغہ سمجھا جائے تو حَاشَ لِلہِ کے معنے ہوں گے وہ خدا کے لئے (اس بات سے) ڈرا اور اس سے دور رہا ہے.ابواالبقاء جلالین کے حاشیہ میں لکھتا ہے حَاشَ لِلہِ فَاعِلُہٗ مُضْمَرٌ.تَقُوْلُ حَاشَ یُوْسُفُ بِخَوْفِ اللہِ.یعنی حَاشَ کا فاعل مضمر ہے اور معنے یہ ہیں کہ یوسف خدا کی خاطر اس فعل سے ڈرا اور اگر یہ حَاشٰی میں سے فعل امر کا صیغہ ہو تو یہ معنے ہوں گے کہ اے مخاطب تو خدا کے لئے اسے دوسروں سے الگ رکھ اور اسے دوسروں جیسا مت سمجھ.یہ ایسی باتوں سے پاک ہے اور اس صورت میں کسرہ بغرض تخفیف فتحہ سے تبدیل شدہ سمجھا جائے گا اور اگر اسے فعلی صیغوں اور تصاریف پر نہ پرکھا جائے بلکہ محاورات اور امثال کی طرح سمجھا جائے تو بھی اس کے معنے یہی ہوں گے جیسا کہ اقرب الموارد کی اوپر کی عبارت میں بحوالہ ایضاح بیان ہوا ہے اس صورت میں بھی بعض نحوی اس کا نام فعل رکھتے ہیں.بعض اسے اسم اور بعض حرف کہتے ہیں اور بعض اسے اسم الفعل کہتے ہیں اور مغنی اللبیب میں ہے وَالصَّحِیْحُ اَنَّہَا اِسْمٌ مُرَادِفٌ لِلْبَرَاءَ ۃِ بِدَلِیْلِ قِرَاءَ ۃِ بَعْضِہِمْ حَاشًا لِلہِ بِالتَّنْوِیْنِ کَمَا یُقَالُ بَرَاءَ ۃً لِلہِ مِنْ کَذَا.وَعَلٰی ھَذَا فَقِرَاءَ ۃُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَاشَ اللہِ کَمَعَاذِ اللہِ یعنی صحیح قول یہ ہے کہ یہ اسم ہے جو بَرَاءَ ۃٌ کا ہم معنے ہے.جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک قِرَاءَ ۃ میں حاشًا لِلہِ بھی آیا ہے جیسا کہ بَرَاءَ ۃً للہِ محاورہ ہے اور اس تحقیق کی رو سے ابن مسعود والی قراء ۃ حاش اللہِ میں معاذاللہ کی طرح حاش مفعول مطلق ہوگا.تفسیر.عزیز کی بیوی کا ان عورتوں کودعوت دینا یعنے اسے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ عورتیں ایسے رنگ میں کلام کررہی ہیں کہ لوگ یہ خیال کریں کہ گویا بدی کا ارتکاب ہو گیا ہے اور بظاہر خیرخواہانہ بات کرتی ہیں لیکن اصل میں بدنام کرنا مقصود ہے تو اسے یہ خیال ہوا کہ ان کے نزدیک عزیز کی بیوی اور یوسف کا تعلق تو ہے، صرف پردہ ڈالنے کے لئے یہ بات بنائی گئی ہے کہ تعلق کوئی نہیں صرف مبادی عزیز کی بیوی کی طرف سے ظاہر ہوئے تھے.پس ان کا یہ شبہ دور کرنے کے لئے اس نے انہیں کھانے یا ناشتہ کی دعوۃ دی.میز وغیرہ لگائی گئی اور ہر اک کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی گئی.(اس سے معلوم ہوتا ہے پرانے زمانہ سے کھانے میں چھریوں کا استعمال چلا آتا ہے اور آج کل کی طرح یہ بھی قاعدہ تھا کہ چھریاں پہلے رکھ دی جاتیں پھر کھانے کی اشیاء آتیں) اس کے بعد یوسفؑ کو حکم دیا کہ ان کے سامنے کھانا وغیرہ رکھے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھی تو شکل سے ہی سمجھ گئیں کہ یوسفؑ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں اور ان کی بزرگی کی قائل ہو گئیں اور سمجھ گئیں کہ ان کا خیال غلط تھا.یوسف علیہ السلام عزیز کی بیوی کے ساتھ شریک کار نہ تھے.ہاتھ کاٹنے سے مراد اور یہ جو فرمایا ہے کہ انہوں نے ہاتھ کاٹے اس کے دو معنے ہوسکتے ہیں ایک تو یہ کہ ان کی
Page 438
سادگی اور شرافت کے نظارہ میں ایسی محو ہوئیں کہ بعض کے ہاتھوں کو چھریوں سے زخم لگ گئے اور یہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں میں انگلیاں حیرت سے دبائیں کہ کیا ہم ایسے شخص کا نام اس طرح لیتی ہیں.چنانچہ عربی میں عَضَّ الْاَنَامِلَ انگلیوں کو دانتوں سے کاٹنے کا محاورہ حیرت کے معنوں میں آتا بھی ہے اور یہ عربی کا محاورہ ہے کہ جزو کے لئے کل کا لفظ بعض دفعہ استعمال کرلیتے ہیں.پس ہوسکتا ہے کہ ایدی انامل کی جگہ استعمال کرلیا گیا ہو.دعوت میں سنگترے طالمود میں جو یہود کی حدیث کی کتاب ہے لکھا ہے کہ عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے سامنے سنگترے رکھے تھے.اور انہیں ان کی خدمت کا حکم دیا وہ ان کی طرف دیکھتی رہیں اور بے توجّہی میں ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے.مَلَکٌ سے مراد بزرگ آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت دیکھ کر وہ عورتیں بے اختیار ان کی نیکی کی قائل ہو گئیں اور کہہ اٹھیں کہ یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے.اس محاورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی فرشتہ کا لفظ انسانوں کے لئے بھی استعمال کرلیا جاتا ہے.قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ١ؕ وَ لَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ (اس پر) اس( عورت) نے انہیں کہا یہ وہی (شخص )ہے جس کے متعلق تم نے مجھے ملامت کی ہے اور میں نے اس نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ١ؕ وَ لَىِٕنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَ سےاس کی مرضی کے خلاف (ایک برا) فعل کروانے کی کوشش ضرورکی تھی( مگر) اس پر (بھی) یہ بچا رہا اور اگر اس لَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ۰۰۳۳ نے وہ بات جس کے لئےمیں اسے حکم دیتی ہوں نہ کی تو یقیناًاسے قید کر دیا جائے گا اور یقیناً ذلیل ہو گا.حلّ لُغَات.اِسْتَعْصَمَ اِسْتَعْصَمَ اِمْتَنَعَ وَاَبٰی بدی کے ارتکاب سے رک رہا اور اس سے انکار کردیا.تَقُوْلُ دُعِیَ اِلٰی مَکرُوْہٍ فَاسْتَعْصَمَ فلاں شخص کو بدی کی طرف بلایا گیا تو اس نے اس کے ارتکاب سے انکار کر دیا.تَحَرّٰی مَایَعْصِمُہٗ ایسی چیز تلاش کی جو اسے بچائے.بِہٖ :اِسْتَمْسَکَ بِہِ ولَزِمَہٗ اسے پکڑ لیا اور اس
Page 439
کے ذریعہ سے اپنا بچاؤ کیا.مِنَ الشَرِّ وَالْمَکْرُوْہِ اِلْتَجَأَ بدی سے بچنے کے لئے کسی چیز کی پناہ لی.(اقرب) لِیَکُوْنًا وَلِیَکُوْنًامیں نون تاکید خفیفہ ہے جسے اس جگہ تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے.صَغُر صَغُرَ ضِدُّ عَظُمَ ذلیل ہوا.ھَانَ بالذُلِّ بے قدر اور ذلیل ہوا.اَلشَّمْسُ مَالَتْ لِلْغُرُوْبِ.سورج نیچے چلا گیا اور ڈوبنے لگا.صَغِرَالْقَوْمَ کَانَ اَصْغَرُھُمْ سب سے چھوٹا ہو گیا.(اقرب) صَغُرَ میں سے صفت مشبہ کا صیغہ صَغِیْرٌ آتا ہے اور صَغِرَ میں سے صَاغِرٌ آتا ہے.پس صَاغِرِیْنَ کے معنے ہوں گے چھوٹے لوگ.یعنی پست اور چھوٹی حیثیت کے لوگ یا ذلیل و رسوا لوگ.الصَّاغِرُ الْمُہَانُ الرَّاضِیْ بِالذُّلِ والضَّیْمِ صَاغِرٌ کے معنے ہیں ذلیل کرکے رکھا جانے والا شخص جو ذلت پرا ور مظلومیت پر راضی ہو اور ذلت میں رہتے رہتے اس کا خود داری کا احساس ہی مارا جائے.(اقرب) تفسیر.عزیز کی بیوی کی زبان سے حضرت یوسف کی بریت پہلے یہ بیان ہوچکا ہے کہ وہ عورتیں اس طرز پر بات کرتی تھیں.جس سے دوسرے لوگ یہ سمجھ لیں کہ فعل بد سرزد ہوا ہے.اور اسی کی تردید کے لئے ان عورتوں کو عزیز کی عورت نے بلایا تھا اور ظاہر ہے کہ جب تک مرد کی طرف سے آمادگی نہ ہو اس فعل کا وقوع نہیں ہوسکتا.پس امرء ۃ العزیز نے پہلے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے لاکر انہی کی زبانوں سے اس کا اقرار کرالیا کہ یوسف سے یہ فعل ہرگز نہیں ہوسکتا.پھر اصل حقیقت بتائی کہ میں نے تو کوشش کی تھی لیکن یہ محفوظ رہا اور جیسا کہ الفاظ آیت سے ظاہر ہے کہ وہ اس کی بدی میں شریک سہیلیاں تھیں.ماضی کی برأۃ کرکے وہ آئندہ کے لئے خود کہتی ہے کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کرا دوں گی اور ذلیل کردوں گی.یہ عجیب لطیفہ ہے کہ مفسرین تو کہتے ہیں کہ وہ بدی کی طرف جھک گئے تھے لیکن وہ عورت جس کا واقعہ ہے اور جس کے لئے یوسف کا انکار نہایت ذلت کا موجب ہے وہ خود کہتی ہے کہ باوجود میری کوشش کے یوسفؑ میرے دام میں نہیں آیا بلکہ محفوظ رہا.قید یوسف ؑ کے لئے ذلت کا موجب نہیں بلکہ عزت کا موجب ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ عزیز کی بیوی نے جس چیز کی دھمکی یوسف کو دی تھی کہ میں ان کو قید کرا دوںگی اور اس طرح یہ ذلیل ہو جائے گا وہی قید یوسف علیہ السلام کی عزت کا موجب ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس قید کے ذریعہ سے بادشاہ کا مقرب اور وزیر خزانہ بنوا دیا.اس کی بات بھی پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس ذریعہ سے اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا اور بتا دیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے.وہ چاہے تو ذلت کے اسباب سے عزت کے سامان پیدا کردے.
Page 440
قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ١ۚ وَ اِلَّا تَصْرِفْ (یہ سن کر) اس نے (دعا کرتے ہوئے )کہا (کہ) اے میرے رب جس بات کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اس کی عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَ اَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ۰۰۳۴ نسبت قید خانہ (میں جانا) مجھے زیادہ پسند ہے اور اگر ان کی تدبیر (کے بد نتیجہ) کو تو مجھ سے نہیں ہٹائے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا.اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا.حلّ لُغَات.اَحَبُّ اَحَبُّ اسم تفضیل کا صیغہ ہے مگر اس کے معنے زیادہ پیارے اور بہت محبوب کے نہیں بلکہ کم مکروہ اور کم مبغوض کا مفہوم مراد ہے.گویا کم بغض کو مجازاً محبت سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ حب اور بغض دو متقابل چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک سے دوری اس کے مقابل کی چیز سے قرب کا موجب ہوجاتی ہے.صَبَا صَبَا یَصْبُوْا صَبْوًا وَصُبُوًّا وَصِبًّا وَصَبَاءً مَالَ اِلَی الصَّبْوَۃِ.جوانی کے جذبات کی طرف جھک گیا.وَمِنْہُ ’’ اَنّ نَفْسَہُ لَتَصْبُوْا اِلَی الْخَیْرِ‘‘.وہ نیکی کے کاموں کی طرف بہت میلان رکھتا اور جھکا رہتا ہے.وَھُوَ یَصْبُوْ اِلٰی مَعَالِی الْاُمُوْرِ.وہ اعلیٰ اور موجب شرف امور کی طرف مائل رہتا ہے.صَبَا اِلَیْہِ صَبْوَۃً وَصُبْوَۃً وصُبُوًّا حَنَّ اِلَیْہِ.اس کا مشتاق ہوا.(اقرب) جَہْلٌ اَلْجَہْلُ عَلٰی ثَلَاثَۃِ اَضْرُبٍ.جہل کی تین قسمیں ہیں.اَلاَوَّلُ خُلُوُّا النَّفْسِ مِنَ الْعِلْمِ.ناواقف اور بے خبر ہونا.اَلثَّانِیْ اِعْتِقَادُ الشَّیْءِ بِخِلَافِ مَاھُوَ عَلَیْہِ کسی امر کے متعلق غلط خیال پر قائم ہونا.اَلثَّالِثُ فِعْلُ الشَّیْ ءِ بِخِلَافِ مَاحَقُّہٗ اَنْ یَّفْعَلَ عملی غلطی کرنا.ا ور جس طرح کرنا چاہیے اس کے برعکس کام کرنا.(مفردات) تفسیر.جس طرح پچھلی آیت سے عزیز کی بیوی کے منہ سے یوسف علیہ السلام کی براء ۃ کرائی گئی ہے یہاں خود حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے ان کی براء ۃ کرائی گئی ہے.وہ کہتے ہیں کہ اے خدا اگر تو ان کے فریب کو مجھ سے نہیں پھرائے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فعل بدی تو الگ رہا اب تک وہ ان کی طرف جھکے بھی نہ تھے.تعجب ہے کہ عورت بھی کہتی ہے کہ یوسف نہیں جھکا یوسف بھی کہتا ہے کہ میں نہیں جھکا دوسری دیکھنے والی عورتیں کہتی ہیں کہ اس سے بدی کا امکان بھی نہ تھا.مگر ہمارے مفسرین ہزاروں سال
Page 441
بعد گھر بیٹھے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جھک تو وہ گیا تھا لیکن پھر ہوشیار ہو گیا.یوسفؑ کے خلاف آنحضرت ؐ کا ہمیشہ خیر ہی کو طلب کرنا اس وقت تک یوسف علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مشابہتیں بیان ہوئی ہیں.اس آیت کے مضمون سے دونوں کی طبیعت کا اختلاف بھی معلوم ہوتا ہے اور اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی ظاہر ہوتی ہے.یوسفؑ ایک مصیبت سے بچنے کے لئے دوسری مصیبت مانگتا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ خدا تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگتے کیونکہ وہ خیر کے ذریعہ سے بھی مصائب کو دور کرسکتا ہے.فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ١ؕ اِنَّهٗ هُوَ پس اس کے رب نے اس کی دعا سن لی اور ان کی تدبیر (کے بد نتیجہ )کو اس سے ہٹا دیا.یقیناً وہی ہے جو بہت ہی السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۰۰۳۵ (دعائیں)سننے والا (اور لوگوں کے حالات کو )خوب جاننے والا ہے.حلّ لُغَا ت.اِسْتِیْجَابٌ اِسْتَجَابَ اللہُ فُلَانًا وَلَہٗ وَمِنْہُ قَبِلَ دُعَاءَ ہُ وَ قَضٰی حاجَتَہٗ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرکے اس کی حاجت پوری کردی.(اقرب) تفسیر.یعنی انہیں اس کی طرف سے مایوس کر دیا.اور یوسفؑ کے دل کو پہلے سے بھی زیادہ تقویّت بخشی.ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى پھر ان (لوگوں) کی (ان) آثار کو دیکھنے کے بعد( یہ) رائے ہو گئی کہ( بدنامی کو دور کرنے کے لئے) وہ اسے حِيْنٍؒ۰۰۳۶ (کم سے کم) کچھ وقت کے لئے ضرور قید کردیں.حلّ لُغَات.بَدَا بَدَالَہٗ فِی الْاَمْرِ نَشَأَ لَہٗ فِیْہِ رَأْیٌ.اسے ایک نئی بات سوجھی.(اقرب) پس اس محاورہ کے مطابق بدَا لَھُمْ میں بَدَا کا فاعل ضمیر مستتر ہے جس کا مرجع رَأْیٌ مقدر ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ جملہ
Page 442
لَیَسْجُنُنَّ مفرد کی تاویل میں ہوکر اس کا فاعل ہو اور اس کی نظیریں بھی بہت پائی جاتی ہیں.تفسیر.یہ قید دعا کے نتیجہ میں نہیں تھی یہ قید یوسف علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں نہ تھی کیونکہ قید کی دعا تو درحقیقت اصل علاج نہ تھا.خدا تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتلایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یوسف کی دعا قبول کرکے اس فریب کو ہٹا دیا جو اس کے خلاف کیا جاتا تھا.اس کے بعد پھر فرماتا ہے کہ پھر ان لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ اسے قید کردیں.پس جب اللہ تعالیٰ نے اس قید کو دعا کی قبولیت میں شامل نہیں کیا تو ہم کیوں کریں.یوسف علیہ السلام نے بے شک قید کی دعا کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اور اچھے ذریعہ سے ٹلا دیا اور اس کی وجہ سے قید نہیں کرایا ہاں بعد میں قید کا معاملہ بعض اور اسباب سے پیدا ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے بعض نشانات دیکھے تو قید کرنے کا فیصلہ کرلیا.اَلاٰیَاتُ سے مراد میرے خیال میں نشانات سے مراد عزیز کی بیوی کی پھیلتی ہوئی بدنامی ہوگی.آخر انہوں نے مناسب سمجھا کہ یوسف کو قید کر دیں تاکہ عزیز کی بیوی کی کھوئی ہوئی عزت قائم ہو جائے اور لوگ اس شبہ میں پڑ جائیں کہ شاید یوسفؑ کا ہی قصور ہوگا.یوسف کو شروع ہی میں قید نہیں کر دیا گیا تھا بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسفؑ کو ابتدائی جھگڑے کے وقت ہی عزیز نے قید کر دیا تھا(پیدائش باب ۳۹ آیت ۱۹ ،۲۰) لیکن قرآن کریم اس کے خلاف قید کو بعد کے حالات کا نتیجہ قرار دیتا ہے مگر جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں بائبل کے ہی حوالہ جات سے بائبل کے بیان کی تردید ہو جاتی ہے.مثلاً پیدائش باب۴۰ (آیت ۲تا۴)میں لکھا ہے کہ وہ دو آدمی جن پر بادشاہ کا عتاب نازل ہوا تھا اور ان کو قید کی سزا دی گئی تھی ان کو اس فوطی فار نے جو جلوداروں کا سردار تھا یوسف کے سپرد کر دیا.جس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو سچا سمجھتا تھا اور انہیں قید میں اس واقعہ کی وجہ سے نہیں بلکہ بعد کے دوسرے حالات کی وجہ سے مصلحتاً ڈالا تھا.وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ١ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اور قید خانہ میں اس کے ساتھ دو اور جوان (بھی) داخل ہو ئے جن میں سے ایک نے (تو اس سے یہ) کہا (کہ) میں اَعْصِرُ خَمْرًا١ۚ وَ قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ (خواب میں)اپنے آپ کو (اس حالت میں) دیکھتا ہوں کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں.اور دوسرے نے کہا( کہ) میں
Page 443
رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ١ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ١ۚ اِنَّا (خواب میں)اپنے آپ کو( اس حالت میں) دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں؎ نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ۰۰۳۷ سے پرندے کھا رہے ہیں (اوران دونوں نے اس سے کہا کہ) آپ ہمیں اس کی حقیقت سے آگا کریں ہم آپ کو یقیناًنیکوکاروں میں سے سمجھتے ہیں.حلّ لُغَات.عَصَرَ عَصَرَ الْعِنَبَ وَنَحْوَہٗ یَعْصِرُ عَصْرًا.اِسْتَخْرَجَ مَاءَ ہٗ اسے نچوڑ کر اس کا رس نکالا.الثَّوْبَ اسْتَخْرَجَ مَاءَ ہٗ بِلَیِّہٖ نچوڑ کر پانی نکالا.الدُّمَّلَ.اِسْتَخْرَجَ مِدَّتَہُ.دبا کر مادہ فاسدہ نکالا.الرِّکْضُ الْفَرَسَ.عَرَّقَہٗ.پسینہ پسینہ کر دیا.اَلشَّیْءَ عَنْہُ: مَنَعَہٗ.اس سے روکا.فُلَانًا اَعْطَاہُ العَطِیَّۃَ.عطیہ دیا.حَبَسَہُ بند کر رکھا.فُلَانٌ عَاصِرٌ مُمْسِکٌ اَوْقَلِیْلُ الْخَیْرِ.بخیل کنجوس اَلْعَصْرُالْعَطِیَّۃُ.عطیہ.(اقرب) پس اَعْصِرُ خَمْرًا کے معنی ہوئے میں انگور نچوڑ کر شراب بناتا ہوں.شراب کا سٹور رکھتا ہوں.شراب دیتا ہوں.تفسیر.دَخَلَ مَعَہٗ کا مطلب مَعَہٗ کے لفظ کے یہ معنے لینے ضروری نہیں کہ جس روز حضرت یوسفؑ قیدخانہ میں داخل ہوئے تھے اسی دن اور اسی وقت وہ بھی داخل ہوئے ہوں.ہاں! یہ ضروری ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قیدخانہ میں رکھے گئے ہوں اور یہ بات بائبل سے ثابت ہے کہ ’’قیدخانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا.‘‘ (دیکھو پیدائش باب ۳۹ آیت ۲۲) اور پھر لکھا ہے کہ ’’اور اس نے ان( دونوں سرداروں) کو نگہبانی کے لئے جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف بند تھا قیدخانہ میں ڈالا‘‘ (پیدائش باب۴۰آیت ۳) پیدائش باب ۴۰ میں یہ خواب ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے مگر مضمون ایک ہی ہے.حضرت یوسف قید خانہ والوں کی نظر میں ان کے خواب کی تعبیر دریافت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قیدخانہ میں ایسا رویہ تھا کہ سب لوگ ان کی بزرگی کے قائل ہو گئے تھے.ورنہ معمولی نیکی کی وجہ سے خوابوں کی تعبیر لوگ دریافت نہیں کرتے.پھر یہ قیدی تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم تجھے اعلیٰ درجہ کے نیکوں خبر اسم جنس ہے اور گو اس کی طرف ضمیر مِنْہُ میں مفرد آئی ہے مگر اردو میں اس کے معنے جمع کرنے ضروری ہیں ورنہ ترجمہ درست نہیں رہ سکتا اس لئے مِنْہُ کا ترجمہ ’’جن میں‘‘ کیا گیا ہے.
Page 444
میں سمجھتے ہیں.قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ اس نے کہا (کہ) جو کھانا تمہیں (اب) دیا جانے والا ہے وہ اس حالت میں ہی تمہارے پاس آئے گا کہ تمہارے قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا١ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ١ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ پاس اس کے پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس (خواب) کی حقیقت بتاچکا ہوں گا یہ( تعبیر رؤیا کی اہلیت مجھ میں) اس مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ وجہ سے (پائی جاتی) ہے کہ میرے رب نے مجھے علم بخشا ہے.میں نے ان لوگوں کے دین کو جو اللہ (تعالیٰ) پر ایمان كٰفِرُوْنَ۰۰۳۸ نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے (بھی) منکر ہیں چھوڑ دیا ہوا ہے.حلّ لُغَات.نَبَّأَ نَبَّأَہُ الْخَبَرَ وَبِالْخَبَرِ: خَبَّرَہٗ.خبر دی.آگاہ کیا.وَیُقَالُ نَبَّأْتُ زَیْدًا عَمْرًا مُنْطَلِقًا.بتایا.علم دیا.اَلنَّبَأُ الْخَبْرُ.خبر.وَقَالَ فِی الْکُلِّیَّاتِ اَلنَّبَأُ وَالْاَنْبَاءُ لَمْ یَرِدَا فِی الْقُرْاٰنِ اِلَّا لِمَا لَہٗ وَقْعٌ وَشَانٌ عَظِیْمٌ.اور کلیات ابوالبقاء میں ہے کہ نَبَأَ کا لفظ یا اَنْبَٓاءُ کا لفظ جہاں بھی قرآن کریم میں آیا ہے کسی ذی عظمت اور ذی شان چیز یا بات کی خبر کے متعلق ہی آیا ہے.(اقرب) ذٰلِکُمَا ذٰلِکُمَابھی ذٰلِکَ کی طرح بعید کے لئے اسم اشارہ ہے.فرق ان میں صرف یہ ہے کہ ذٰلِکُمَا سے صرف اسی موقع پر اشارہ کیا جاتا ہے جب مخاطب دو شخص ہوں اور ذٰلِکَ کا استعمال وسیع ہے جو واحد شخص کو مخاطب کرتے وقت بھی بولا جاتاہے اور کثیر کو مخاطب کرتے ہوئے بھی.یہ لفظ دراصل تین لفظوں سے مرکب ہے یعنے ذا،لام اور کاف سے.ذَا اسم اشارہ ہے.لام جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اس کے مقام یا درجہ کے بُعد پر دلالت کرتا ہے اور کاف مخاطب کی علامت ہے.(اقرب) تفسیر.حضرت یوسف ؑ کا ان قیدیوں کو تسلی دینا کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے میں عجیب حکمت سے کام لیا ہے.چونکہ خطرہ تھا کہ تبلیغ کرنے پر
Page 445
وہ گھبرائیں گے اس لئے پہلے انہیں تسلی دے دی کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بلکہ کھانا آنے سے پہلے ہی تم کو فارغ کردو ںگا.یہ اس لئے کیا کہ وہ گھبرا نہ جائیں اور غور سے سنتے رہیں.معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں بھی قیدیوں کو کھانے سے پہلے کچھ رخصت ملا کرتی تھی تا وہ آپس میں بات چیت کرلیں جیسا کہ آج کل بھی دستور ہے.بارھویں مشابہت آنحضرت ؐ نے بھی کفار مکہ کو کھانے کے موقع پر تبلیغ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہت ہے.معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع نہیں ملتا تھا.انہوں نے ان کے سوال کو غنیمت جانا اور سمجھ لیا کہ ان کی ضرورت کے پورا ہونے سے پہلے تبلیغ کروں گا تو یہ سننے پر مجبور ہوں گے.ایسا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا.آپ ابتداء دعویٰ میں اَعیانِ مکہ کو تبلیغ کرنا چاہتے تو وہ لوگ کترا جاتے اور تبلیغ نہ سنتے.آخر آپؐ نے ان لوگوں کی دعوت کی اور کھانا کھلا کر تبلیغ کرنی چاہی مگر وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے.اس پر آپؐ نے یہ تدبیر کی کہ پھر دعوت کی اور کھانا آنے سے پہلے ان کو اپنے دعویٰ سے آگاہ کر دیا.وہ لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھنے پر مجبور تھے اس لئے آپ کو اپنی بات سنانے کا موقع مل گیا.وعظ و نصیحت کو مخاطب کے ملال کا موجب نہ بننے دینا چاہیے اس آیت سے انبیاء کے وعظ کا طریق بھی معلوم ہوتا ہے.پس ان کی اتباع میں وعظ و نصیحت کرتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بات کہی بھی جائے اور دوسرے پر گراں بھی نہ گزرے.مذہب وہی سچا ہے جو ہر وقت تازہ پھل دے ’’یہ وہ علم ہے جو مجھے خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے.‘‘ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ثبوت دیا ہے کہ جس مذہب پر میں کاربند ہوں وہی سچا ہے کیونکہ اس کے تازہ پھل انسان کو ملتے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے.وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ١ؕ مَا اور میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی پیروی( اختیار) کی ہے.ہمیں کسی چیز کو بھی كَانَ لَنَاۤ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ١ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللہ (تعالیٰ)کا شریک ٹھہرانے کا حق نہیں ہے یہ (توحید کی تعلیم کا ملنا) ہم پر اور (دوسرے )لوگوں پر اللہ( تعالیٰ)
Page 446
اللّٰهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ۰۰۳۹ کا (اس کے خاص فضلوں میں سے) ایک فضل ہے لیکن اکثر لوگ (اس کے احسانوں کا) شکر نہیں کرتے.تفسیر.تعلق باللہ کے دروازہ کا کھلا ہونا بہت بڑا فضل الٰہی ہے یعنی جس مذہب پر میں ہوں اس کے ذریعہ سے ہمیشہ سے لوگ خدا تعالیٰ سے تعلق پید اکرتے چلے آئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایسا راستہ بندہ کے لئے کھلا رکھا ہے لیکن افسوس کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کی لوگ قدر نہیں کرتے.نبی بھیجنے کا انعام تمام قوم کے لئے ہوتا ہے عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ کہہ کر بتایا ہے کہ نبوت کا انعام صرف اسی شخص کے لئے نہیں ہوتا جسے نبوت ملے بلکہ درحقیقت وہ سب دنیا کے لئے ہوتا ہے.سب ہی علیٰ قدرمراتب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں.حتیٰ کہ اگر غور کیا جائے تو کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں.نبی کے بعد کئی فضول عقائد جن کو وہ رد کرتا ہے یہ لوگ ترک کردیتے ہیں.گو نبی کی صداقت کا انکار ہی کرتے رہیں.يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ۠ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ اے( میرے) قید خانہ کے دونوں ساتھیو.کیا( ایک دوسرے سے) اختلاف رکھنے والے خدا بہتر ہیں یا اللہ( تعالیٰ) الْوَاحِدُ الْقَهَّارُؕ۰۰۴۰ جو یکتا(اور) کامل غلبہ رکھنے والا ہے.حل لغات.قَھَرَ قَھَّارٌکا لفظ قَھَرَ میں سے اسم فاعل کا صیغہ مبالغہ ہے.قَھَرَہٗ قَھْرًا غَلَبَہٗ فَھُوَ قَاھِرٌ.اس پر غالب ہوا.وَتَقُوْلُ اَخَذْتُہُمْ قَھْرًا اَیْ مِنْ غَیْرِ رِضَاھُمْ.اور اَخَذْتُہُمْ قَہْرًا کے معنے ہیں بغیر ان کی مرضی کے زبردستی ان کو پکڑ لیا.اَلْقَہَّارُ فَعَّالٌ لِلْمُبَالَغَۃِ وَاِسْمٌ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی.قَھَّار اسم فاعل سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور خدا تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے.تفسیر.قید کی حالت میں یوسف کا اللہ تعالیٰ کی صفت احسان کے ذکر پر زور دینا فرمایا کہ دنیا میں غلبہ جتھے کے ساتھ ہوا کرتا ہے مگر میرے رب کا معاملہ بالکل نرالا ہے.وہ اکیلا بھی ہے اور ساتھ ہی غالب.بلکہ بڑا غالب بھی.
Page 447
اس قید کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ پر اس قسم کا زور دینا حضرت یوسف علیہ السلام کے کمالات باطنی کا مظہر ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے.مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلَّاۤ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَاۤ اَنْتُمْ وَ تم اسے چھوڑ کر سوائے چند( فرضی) ناموں کے جو (خود) تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے بنا رکھے ہیں (اور) اٰبَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ١ؕ اِنِ الْحُكْمُ جن کی بابت اللہ (تعالیٰ) نے (تمہاری تائید میں) کوئی بھی (تو) حجت نہیں اتاری.(کسی کی) عبادت نہیں کرتے اِلَّا لِلّٰهِ١ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ١ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ (یاد رکھو) فیصلہ کرنا اللہ (تعالیٰ) کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے( اور) اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی الْقَيِّمُ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ۰۰۴۱ کی عبادت نہ کرو.یہی درست مذہب ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں.حلّ لُغَات.اَلْقَیِّمُ.دِیْنًاقَـیِّـمًا اَیْ ثَابِتًا مُقَوِّمًا لِاُمُوْرِ مَعَاشِہِمْ وَمَعادِھِمْ.دِیْنٌ قَیِّمٌ ثابت اور قائم رہنے والے اور دنیا اور آخرت کے امور کو درست کرنے والے دین کو کہتے ہیں.(مفردات) اَلْقَیِّمُ عَلَی الْاَمْرِ مُتَوَلِّیْہِ.جو کسی کا متولی ہو.اَلْقَیِّمَۃُ الدِّیَانَۃُ الْمُسْتَقِیْمَۃُ.صحیح راستہ.درست مذہب (اقرب) تفسیر.جو امور منجانب اللہ ہوں ان کے ساتھ دلیل اور غلبہ کا ہونا ضروری ہے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا وجود صرف اس امر پر مبنی ہو کہ تم نے ایک نام تجویز کرلیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل اور غلبہ ان کے ساتھ نہیں ہے تم ان کی عبادت کرکے کیا لو گے اور ایسی چیزوں کی عبادت کیا نفع پہنچا سکتی ہے؟ اس آیت میں اس اصل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو امور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل اور غلبہ بھی ہونا چاہیے.مختلف مذاہب یونہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور کوئی فیصلہ کی اس یقینی راہ کی طرف توجہ نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مدعی کو کیا دلیل ملی ہے.عقل کب اس امر کو تسلیم
Page 448
کرسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مذہب اپنے ثبوت کے لئے انسانی اور خالص عقلی دلائل کا محتاج ہو.جو چیز آسمان سے آئے اس کے لئے آسمانی دلیل کی بھی ضرورت ہے.دین وہی سچا ہے جو دنیا و آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرے دِیْنِ قَیِّم کہہ کر بتایا ہے کہ دین وہی سچا ہوسکتا ہے جو دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرے اور ایسی تعلیم دے جس سے انسان کی روحانی اور جسمانی دونوں حالتیں درست ہوں.دین وہی سچا ہے جو شرک سے بچائے اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ایسا دین وہی ہوسکتا ہے جو شرک سے لوگوں کو بچائے.یہ ایک زبردست صداقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک انسانی ترقی کے راستہ میں روک ہے.بھلا جو قوم عناصر کو خدا سمجھے گی وہ ان کو چیر پھاڑ کر اپنی خدمت میں کب لگائے گی.قوانین قدرت سے تو وہی قوم فائدہ اٹھائے گی جو سب کائنات کو خدا کی مخلوق اور اپنی خدمت کے لئے پیدا کی ہوئی چیز سمجھے گی.يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا١ۚ وَ اَمَّا اے( میرے) قید خانہ کے دونوں ساتھیو(اب اپنی اپنی خواب کی تعبیر سنو) تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ١ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ پلایاکرے گااور دوسرے کو سولی دے کر مارا جائے گا.پھر پرندے اس کے سر پر سے (گوشت وغیرہ) کھائیں گے الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِؕ۰۰۴۲ ( لو) جس امر کے متعلق تم پوچھ رہے ہو اس کا فیصلہ کر دیا گیاہے.حلّ لُغَا ت.صَلَبَ صَلَبَہٗ.اَیْ اَلْقَاتِلُ کَضَرَبَہٗ صَلْبًا جَعَلَہٗ مَصْلُوْبًا.اسے مصلوب کر دیا.وَفِی لِسَانِ الْعَرَبِ وَالصَّلْبُ ھٰذِہِ الْقِتْلَۃُ الْمَعْرُوْفَۃُ اور لسان العرب میں ہے کہ صلب کے معنے صلیب کی موت سے مارنے اور قتل کردینے کے ہیں.وَاَصْلُہٗ مِنَ الصَّلِیْبِ وَھُوَ الْوَدَکُ.اور اسی کا ماخذ صلیب ہے.جس کے معنے چربی کے اور ہڈیوں کے گودے کے ہیں.صَلَبَ اللَّحْمَ شَوَاہُ فَأَسَالَہٗ اَیْ اَلْوَدَکَ مِنْہُ گوشت کو سیخوں وغیرہ پر بھونا.جس کی وجہ سے اس کی چربی نیچے گرتی رہی.صَلَبَ العِظَامَ جَمَعَہَا وَطَبَخَہَا وَاسْتَخْرَجَ
Page 449
وَدَکَہَا لِیُؤَتَدَمَ بِہٖ.ہڈیوں کو گوشت سے الگ جمع کرکے اور انہیں پکا کر ان کا گودا سالن کے طور پر کھانے کے لئے نکالا.وَالصَّلِیْبُ اَلْوَدَکُ.اور صلیب کے معنے چربی اور گودے کے ہیں.وَفِی الصِّحَاحِ وَدَکُ الْعِظَامِ اور صحاح میں ہے کہ صلیب ہڈیوں کے گودے کو کہتے ہیں.وَبِہٖ سُمِّیَ الْمَصْلُوبُ اور اسی وجہ سے مصلوب کو مصلوب کہتے ہیں.لِمَایَسِیْلُ مِنْ وَدَکِہٖ کیونکہ اس کی چربی اور گودا نکل کر بہتا ہے وَالصَّلْبُ ھٰذِہِ الْقِتْلَۃُ الْمَعْرُوْفَۃُ اور اسی طریق پر قتل کرنے اور ہڈیوں کا گودا نکالنے کو صلب کہتے ہیں.مُشْتَقٌّ مِنْ ذٰلکَ.یہ لفظ اسی لفظ صلیب (چربی اور ہڈیوں کا گودا) سے ماخوذ ہے.لِاَنَّ وَدَکُہٗ وَصَدِیْدَہٗ یَسِیْلُ کیونکہ مصلوب کی چربی اس کی ہڈیوں کا گودا اور اس کی پیپ نکل کر بہتی ہے.(تاج العروس) تفسیر.خواب کے پورا ہونے میں اس کی تعبیر کا بھی بہت دخل ہوتا ہے اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو تعبیر کرنے والے تھے.پھرا نہوں نے یہ کیوں کہا کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا بھی اس کے پورا ہونے سے بہت کچھ تعلق ہوتا ہے.جب تک خواب سنائی نہیں جاتی اسے زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی.لیکن جب سنائی جاتی ہے اور اس کی تعبیر ہوجاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی غیرت ہوجاتی ہے اور وہ حتی الوسع ضرور پوری کی جاتی ہے.اسی وجہ سے صوفیاء نے لکھا ہے بلکہ احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ بری خواب سنانی نہیں چاہیے(بخاری کتاب التعبیر باب اذارأی ما یکرہ ولا یخبر بھا ولا یذکر بھا).پس جب ان لوگوں نے خوابیں حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا دیں اور انہوں نے تعبیر کر دی تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب یہ خوابیں پوری ہوکر رہیں گی.وَ قَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ١ٞ اور ان میں سے اس سے جس کے متعلق اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ مخلصی پا جانے والا ہے اس نے کہا( کہ) اپنے آقا فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ کےپاس میرا (بھی) ذکر کرنا.پھر شیطان نے اس( آزاد شدہ قیدی) کو اس کے آقا سے (یہ) ذکر کرنا فراموش
Page 450
سِنِيْنَؕؒ۰۰۴۳ کرا دیا.اور( اس کی اس غفلت کی وجہ سے) وہ (یعنے یوسفؑ) کئی سال قید خانہ میں (پڑا) رہا.حلّ لُغَات.بِضْعٌ.اَلْبِضْعُ مَابَیْنَ الثَّلَاثِ اِلَی التِّسْعِ.تین سے لے کر نو تک کو بِضْعٌ کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.ذِکْرَ رَبِّہٖ کے معنی.(اپنے آقا کے پاس ذکر کرنا) حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے جس کی نسبت انہیں یقین تھا کہ بچ جائے گا یہ کہاکہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا کہ فلاں شخص کو قید میں بلاوجہ ڈالا ہوا ہے.لیکن اس شخص کو اپنے برے مشاغل یعنی شراب پلانے کے کام میں یہ خیال نہ رہا کہ ذکر کرتا.بعض مفسرین نے اس جگہ یہ معنے کئے ہیں کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کا ذکر بھلا دیا.یعنی انشاء اللہ کہنا یاد نہ رہا حالانکہ یہ موقع انشاء اللہ کہنے کا تھا ہی نہیں.ا س آیت میں جب رب کا لفظ بادشاہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کو خدا تعالیٰ سے غافل ثابت کیا جاتا.اس کے سیدھے معنے یہ ہیں کہ اس شخص کو اپنے بادشاہ سے یوسف کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا.یعنی اپنے شیطانی کاموں میں پڑ کر یوسف علیہ السلام کی صحبت کا نیک اثر جاتا رہا.اور یوسفؑ کا خیال اسے نہ آیا اور بادشاہ کے پاس اس کا ذکر نہ کرسکا.ایسے صاف معنوں کی موجودگی میں کہ جن سے یوسف علیہ السلام کی برأت پر بھی کوئی الزام نہیں لگتا ہمیں دوسرے معنے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ظَنَّ کا لفظ اختیار کرنے کی وجہ ظَنَّ کا لفظ اس لئے کہا کہ غیر نبی کی خواب کتنی بھی یقینی کیوں نہ ہو شبہ سے خالی نہیں ہوسکتی اور اس کو ظن سے ہی بیان کیا جاسکتا ہے.صرف نبی ہی کی یہ شان ہے کہ اس کے الہام پر قسم کھائی جاسکتی ہے کہ وہ سچا ہے اور کسی کے الہام یا خواب کو یہ شرف حاصل نہیں اور یہ بھی نبی اور غیر نبی کے الہام میں ایک فرق ہے.
Page 451
وَ قَالَ الْمَلِكُ اِنِّيْۤ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ اور( کچھ عرصہ کے بعد) بادشاہ نے (اپنے درباریوں سے) کہا (کہ) میں( خواب میں) سات موٹی گائیں دیکھتا سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ١ؕ ہوں جنہیں سات دبلی (گائیں) کھا رہی ہیں اور سات( ترو تازہ اور) سبز بالیں (دیکھتا ہوں) اور چند اور (بالیں يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ۰۰۴۴ بھی جو) خشک (ہیں) اے سر کردہ لوگو!اگر تم رؤیا کی تعبیر (کیا) کرتے ہو تو مجھے میری(اس) رؤیا کے متعلق ( صحیح) حکم بتاؤ.حلّ لُغَات.عَـجِفَ عَـجِفَتِ الشَّاۃُ عَـجَفًا ذَھَبَ سِمَنُہَا وَضَعُفَتْ دبلی ہو گئی.وَالْبِلَادُ لَمْ تُمْطَرْ فلاں علاقہ میں بارش نہ ہوئی اور اس میں خشک سالی رہی.وَمِنْہُ نَزَلُوْا فِیْ بِلَادٍ عِـجَافٍ اَیْ غَیْرِ مَمْطُوْرَۃٍ جب شہروں کے لئے لفظ عجاف آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں جن پر بارش نہیں برسی.اسی طرح جب دانوں کے لئے یہ لفظ آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ دانے چھوٹے رہ گئے.اَلْعَـجَفُ الْھُزَالُ.دُبلا پن.اَلْاَعْـجَفُ اَلْمَہْزُوْلُ وَھِیَ عَـجْفَاءُ جَمْعُہٗ عِـجَافٌ شَاذٌ.اس سے صفت کا صیغہ مذکر اَعْـجَفُ اور مؤنث عَـجْفَاءُ آتا ہے.اور ان کی جمع دوسرے اس قسم کے الفاظ کے خلاف بجائے عُـجْفٌ کے عـجَافٌ آتی ہے.(اقرب) عَبَرَ عَبَرَالسَّبِیْلَ عُبُوْرًا شَقَّہَا.اَیْ مَرَّکأَنَّہٗ شَقَّہَا وَقَطَعَہَا.وہ راستہ پر ایسی سرعت سے گزرا اور سیدھا چلا کہ گویا اس نے اسے چیر دیا اور اسے کاٹتا ہوا اس میں گزرا.بِفُلَانٍ الْمَاءَ جَازَ دریا کے پار پہنچا دیا.الْکِتَابَ تَدَبَّـرَہٗ فِی نَفْسِہٖ وَلَمْ یَرْفعْ صَوْتَہٗ بِقِرَاءَ تِہٖ دل میں الفاظ پر غور کرتا گیا.اَلرُّؤْیَا عَبْرًا وَعِبَارۃً فَسَّرَھَا وَاَخْبَرَبِاٰخِر مَایَؤُوْلُ اِلَیْہِ اَمْرُھَا.خواب کا نتیجہ بتایا اس کی تعبیر بتائی.(اقرب) اَفْتٰی اَفْتَاہُ الْعَالِمُ فِی مَسْئَلَۃٍ.اَبَانَ لَہُ الحُکْمَ فِیْہَا وَاَخْرَجَ لَہٗ فِیْہَا فَتْوٰی.عالم نے پیش آمدہ مسئلہ کے متعلق فتویٰ دیا اور اس کا حکم بتایا.(اقرب) تفسیر.فرعون پر اس کی رؤیا کا گہرا اثر معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو اپنی رؤیا پر اس قدر یقین تھا کہ وہ صرف تعبیر ہی نہیں پوچھتا بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ تعبیر معلوم ہوچکنے کے بعد کرنا کیا چاہیے.معلوم ہوتا ہے کہ
Page 452
اللہ تعالیٰ نے اسے رؤیا ایسی وضاحت اور ہیبت کے ساتھ دکھائی تھی کہ اس کا نقشہ اس کے دل پر اثر کر گیا تھا.پس وہ مجبور تھا کہ اسے سچا سمجھے اور اس کے نتائج سے بچنے کی کوشش کرے.اگر اس شان سے رؤیا نہ ہوتی اور اس کے دل پر گہرا اثر نہ ہوتا تو وہ دربار میں اس کا ذکر نہ کرتا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت نہ پیدا ہوتی.قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ١ۚ وَ مَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ۰۰۴۵ انہوں نے کہا (کہ یہ تو) پراگندہ خوابیں ہیں اور ہم( لوگ) ایسی پراگندہ خوابوں کی حقیقت نہیں جانتے.حلّ لُغَات.ضِغْثٌ اِلضِّغْثُ مِنَ الْخَبَرِ مَاکَانَ مُخْتَلِطًالَا حَقِیْقَۃَ لَہٗ.ضِغْثٌ اس خبر یا بات کو کہتے ہیں جو پراگندہ ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو.اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ اَحْلَامٌ مُلْتَبِسَۃٌ لَا یَصِحُّ تَأْوِیْلُہَا لِاِخْتِلَاطِہَا اضغاث احلام ایسی پراگندہ خوابوں کو کہتے ہیں جن کی سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ کی وجہ سے تعبیر نہیں کی جاسکتی.(اقرب) حُلْمٌ اَحْلَامٌ حُلُمٌ کی یا حُلْمٌ کی جمع ہے.مَایَرَاہُ النَّائِمُ فِی نَوْمِہٖ.لٰکِنَّہٗ قَدْ غَلَبَ عَلٰی مَا یَرَاہُ مِنَ الشَّرِّ وَالْقَبِیْحِ کَمَا غَلَبَتِ الرُّؤْیَا عَلٰی مَایَرَاہُ مِنَ الْخَیْرِ وَالْحَسَنِ وَرُبَّمَا یُسْتَعْمَلُ کُلٌّ مَکَانَ الْآخِرِ حُلْمٌ اس نظارہ کو کہتے ہیں جو انسان نیند کی حالت میں دیکھے لیکن یہ لفظ عام طور پر برے اور قبیح نظارہ کے لئے بولا جاتا ہے جس طرح رؤیا کا لفظ عام طور پر اچھے اور نیک نظارہ کو کہتے ہیں.لیکن کبھی کبھی یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی بول لئے جاتے ہیں.(اقرب) مجمع البحار میں لکھا ہے اَلرُّؤْیَا مِنَ اللہِ وَالحُلُمُ مِنَ الشَّیْطَانِ ھُمَا مَایَرَاہُ النَّائِمُ لٰکِنْ غَلَبَ الرُّؤْیَا عَلَی الْخَیْرِ وَالْحُلُمُ عَلَی الشَّرِّ وَالْقَبِیْحِ.یعنی رؤیا اورحلم دونوں لفظوں کے اصل معنے حالت خواب میں دیکھنے کے ہیں لیکن عام محاورہ اور استعمال میں حلم بری خواب کو کہتے ہیں اور رؤیا اچھی کو.جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اَلرُّؤْیَا مِنَ اللہِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّیْطٰنِ.یعنی رؤیا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور حلم شیطان کی طرف سے.(اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والی خواب آتی ہی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اکثر ڈرانے والی خوابیں آتی رہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوں گی.بلکہ شیطان کی طرف سے ہوں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رحم اس کے غضب پر غالب ہے.اور جس کو اکثر اچھی خوابیں آئیں وہ سمجھے کہ وہ خوابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں کیونکہ ان میں رحمت کا پہلو غالب ہے.
Page 453
دوسرے معنے ا س کے یہ ہیں کہ حلم یعنی برے خوابوں کا موجب شیطان ہے اور رؤیا یعنی اچھے خوابوں کا موجب اللہ تعالیٰ ہے.یعنی عذاب کا سبب شیطانی تعلق ہوتا ہے اور فضل و برکت کا سبب رحمانی تعلق ہوتا ہے.گویا یہ بتایا ہے کہ اگر بری خوابیں اور ڈراؤنے منظر دیکھو تو سمجھ لو کہ شیطان سے تعلق پیدا ہو گیا ہے اور اپنی اصلاح کرو.اور اگر اچھے منظر دکھائے جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے اور فضل کرنا چاہتا ہے.پس نیکی میں اور ترقی کرو.تفسیر.وہی خواب قابل تعبیر ہوتی ہے جس میں جھوٹ کی ملونی نہ ہو قَالُوْۤا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ.انہوں نے کہا کہ یہ خوابیں بری بھی ہیں اور مخلوط بھی.یعنی سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہے.دماغی دخل سے پاک نہیں ہیں.اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہی جاسکتیں اس لئے ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں کی جاسکتی.کیونکہ جب تک جھوٹ اور سچ الگ الگ نہ ہو تعبیر کے متعلق حکم نہیں لگایا جاسکتا.یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم احلام کی تعبیر نہیں جانتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بری خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کرسکتے بلکہ اَحْلَام کے اوپر جو ال ہے وہ عہد ذہنی کا ہے یعنی اس سے اشارہ اضغاث احلام کی طرف ہے اور مراد یہ ہے کہ جس قسم کی پراگندہ خوابوں کا ذکر ہم پہلے کرچکے ہیں ویسی خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کرسکتے نہ یہ کہ خالی ڈراؤنی خواب کی تعبیر ہم نہیں کرسکتے.وَ قَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَ ادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ اور ان (دو قیدیوں) میں سے اس نے جس نے مخلصی پائی تھی اور( جس نے) ایک عرصہ کے بعد (یوسفؑ کے ساتھ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ۰۰۴۶ جو اس کامعاملہ گزرا تھا اسے )یاد کیا کہا (کہ )میں تمہیں اس کی حقیقت سے آگاہ کروں گا پس تم (اس کی حقیقت دریافت کرنے کے لئے) مجھے بھیجو.حلّ لُغَات.اِدَّکَرَ.اِدَّکَرَ ذَکَرَ میں سے باب افتعال کا فعل ماضی ہے.اِدَّکَرَہٗ ذَکَرَہٗ.اس نے یاد کیا.اسے یاد آیا.(اقرب) اُمَّۃٌ الْاُمَّۃُ الْحِیْنُ.وقت عرصہ.(اقرب) وَقَوْلُہٗ تَعَالٰی وَادَّکَرَ بَعْدَ اُمّۃٍ اَیْ حِیْنٍ کچھ عرصہ کے بعد.وَقَدْ قُرِیَٔ بَعْدَ أَمَّۃٍ اَیْ بَعْدَ نِسْیَانٍ اور ایک قِرَاءَ ۃ میں أمَّہٌ بھی آیا ہے جس کے معنے ہیں بھول جانے کے بعد.وَحَقِیْقَۃُ ذٰلِکَ بَعْدَ انْقِضَاءِ اَھْلِ عَصْرٍ اَوْاَھْلِ دِیْنٍ اور اس کے اصل معنے عرصہ دراز کے ہیں.جس میں ایک
Page 454
زمانہ کے لوگ یا ایک دین کے اور ایک قرن کے لوگ گزر جائیں.(مفردات) تفسیر.بچائے جانے والے شخص کا اس خواب کی تعبیر دریافت کرنے کی طرف توجہ دلانا مجھے بھیجو کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی بڑے سرداروں میں سے نہ تھا اور بادشاہ کے قول کا مخاطب نہ تھا.جب وہ لوگ اس خواب کی تعبیر نہ کرسکے اور انہوں نے پراگندہ خواب کہہ کر جس میں خیالات کی ملونی ہو گئی ہو اپنا پیچھا چھڑایا تو اس شخص کو اپنا اور اپنے ساتھی کا خواب یاد آیا اور خیال گزرا کہ ہمارے خواب بھی بظاہر پراگندہ معلوم دیتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی معقول تعبیر کی اور اسی طرح ہو گیا.ممکن ہے وہ ان خوابوں کی بھی تعبیر کرسکیں اور امراء دربار سے اجازت چاہی کہ اگر مجھے جانے کی آپ لوگ اجازت دیں تو میں جاکر اس خواب کی تعبیر پوچھ آتا ہوں.پرانے زمانہ میں بادشاہوں کے درباری زیادہ تر کاہن اور مذہبی لوگ ہی ہوتے تھے اس امر پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ بادشاہ امراء دربار سے تعبیر کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ پرانے زمانہ میںکاہنوں اور مذہبی آدمیوں کا خاص زور ہوتا تھا اور انہی میں سے عام طور پر امراء دربار مقرر کئے جاتے تھے.حضرت یوسف ؑکے اور آنحضرت ؐ کے طریق کامیابی میں فرق اس آیت کے متعلق یہ لطیف امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کامیابی تو یوسف علیہ السلام کو بھی ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مگر طریق کامیابی دونوں کے الگ الگ تھے.یوسف علیہ السلام کو دوسروں کے ذریعہ سے ترقی دلانی تھی اس لئے ان کے لئے دوسروں کو ہی خواب دکھائی.مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بلاواسطہ ترقیات ملنی تھیں اس لئے ان کی ترقی کی خبر بھی براہ راست انہی کو ملتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پسند کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کی آخری منازل کسی اور شخص کی مدد سے طے ہوں.يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ (اور اس نے یوسفؑ سے جا کر کہاکہ) اے یوسف! (ہاں) اے راستباز ! ہمیں ان سات گائیوں (کو رؤیا میں يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ دیکھنے) کے متعلقجنہیں سات دبلی (گائیں) کھا جائیں اور (نیز) سات سبز بالوں اور( ان کے مقابل پر) چند
Page 455
يٰبِسٰتٍ١ۙ لَّعَلِّيْۤ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ۰۰۴۷ اور خشک (بالوں کو دیکھنے) کےمتعلق حکم بتائیے تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں کہ ان کو( بھی تیری صداقت کا) علم ہو جائے.حلّ لُغَات.صِدِّیْقٌ.صِدِّیْقٌ صَدَقَ میں سے اسم فاعل سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنے ہیں اَلْکَثِیْرُ الصِّدْقِ.بڑا راست گو.اَلدَّائِمُ التَّصْدِیْقُ.اَلْکَامِلُ فِیْہِ.سچائی کو فوراً مان لینے والا.اَلَّذِیْ یُصَدِّقُ قَوْلَہُ بِالْعَمَلِ جس کے قول کی اس کے فعل سے تصدیق ہوتی ہو.(اقرب) تفسیر.لَعَلّی اَرْجِعُ میں لفظ لَعَلَّ کے لانے کی وجہ فرعون کا ساقی حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ شاید میں ان لوگوں کی طرف لوٹوں.حالانکہ شاید کا کوئی موقع نہ تھا.یوسف علیہ السلام اسے قیدخانہ میں نہیں رکھ سکتے تھے.پس اس جگہ پر لَعَلَّ مخاطب کی طمع کے لئے آیا ہے یعنی اگر میں اس تعبیر کو لے کر ان کی طرف لوٹوں تو انہیں آپ کے کمالات کا علم ہو جائے گا اور آپ کی براء ت ان پر ظاہر ہو جائے گی.تعبیر دریافت کرنے والے شخص کا اپنی غفلت کے متعلق عذر کا اظہار اس کلام سے اس شخص نے اپنی براء ت بھی کی ہے.وہ وعدہ کر گیا تھا کہ میں فرعون سے ذکر کروں گا لیکن اس نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا.اب وہ اس فقرہ سے کہ تاکہ وہ جان لیں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ گویا اس سے پہلے ان سے بات کرنی مناسب نہ تھی کیونکہ کامیابی کی امید نہ تھی اب موقع نکلا ہے کہ انہیں آپ کی براء ت کا قائل کیا جاسکے تو میں فوراً آپ کے پاس آگیا ہوں.تیرھویں مشابہت آنحضرت ؐ نے بھی سات سال کے قحط کی خبر دی تھی اس واقعہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے.جس طرح یوسفؑ کے زمانہ میں سات سال کے قحط کی خبر دی گئی تھی اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سات سال کے قحط کی خبر دی تھی.جب مکہ والوں نے آپؐ کو بار بار عذاب لانے کے لئے کہا اور آپؐ پر طرح طرح کے اتہام لگائے تو جیسا کہ ابن مسعود سے صحیحین میں روایت ہے دَعَا عَلَیْہِمْ بِسَنِیْنَ کَسَنِی یُوْسُفَ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے لئے ویسے ہی سالوں کی دعا کی جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں گزرے تھے.یعنی ویسے ہی شدید قحط کی آپؐ نے دعا کی.چنانچہ حجاز
Page 456
میں سخت قحط پڑا اور سات سال تک رہا.یہاں تک کہ بعض لوگ ان ایام میں مردار وغیرہ کھانے لگے اور صحتیں اس قدر بگڑ گئیں کہ آنکھوں کے آگے دھوئیں نظر آنے لگے.آخر سات سال کی تکلیف کے بعد لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپؐ مُضَر یعنی قبائل حجاز کے لئے دعا کریں کہ وہ بالکل تباہ ہو گئے ہیں.آپؐ نے دعا کی اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بارش کی اور قحط دور ہوا(بخاری کتاب التفسیر سورۃ الدخان ).قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا١ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ اس نے کہا (کہ) تم سات برس مسلسل جدوجہد سے کاشت (کا کام) کرو گے پس (اس عرصہ میں) جو (کچھ) تم فِيْ سُنْۢبُلِهٖۤ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ۰۰۴۸ کاٹو اس( سب)کوسواء( اس) تھوڑے سے حصہ کے جو تم کھا لو اس کی بالوں میں ہی رہنے دینا.حلّ لُغَات.دَأْبٌ دَأَبَ فِیْ عَمَلِہٖ جَدَّوَتَعِبَ وَاسْتَمَرَّ عَلَیْہِ.انتہائی حد تک محنت اور کوشش کی اور بلاوقفہ اس پر قائم رہا.(اقرب) پس دَاَ بًا کے معنی ہوئے متواتر محنت اور مشقت کے ساتھ تم اس کام میں مصروف رہوگے.ذَرَّ ذَرُوْا فعل امر ہے جس کے معنے ہیں چھوڑ و.اس مادہ میں سے صرف فعل امر اور فعل مضارع استعمال ہوتا ہے.فعل ماضی، مصدر اور اسمائے مشتقہ جیسے اسم فاعل وغیرہ نہیں ہوتے.چنانچہ اقرب الموارد میں ہے ذَرْہُ أی دَعْہُ اسے چھوڑ دے.وَاَمَاتَتِ الْعَرَبُ مَاضِیَہٗ وَمَصْدَرَہٗ وَاسْمَ الْفَاعِلِ مِنْہُ اور عرب لوگ اس کی ماضی اور مصدر اور اسم فاعل کو استعمال نہیں کرتے بلکہ جب ان مادوں کے استعمال کی ضرورت ہو تو ترک کا لفظ استعمال کرلیتے ہیں.(اقرب) تفسیر.تَزْرَعُوْنَ بمعنے فعل امر ہے گو الفاظ یہ ہیں کہ تم ایسا کرو گے مگر مراد یہ ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہوگا تاکہ قحط کے ایام کے لئے غلہ موجود رہے.اگر ان دنوں میں محنت سے کام نہ لیا اور پھر احتیاط سے غلہ خرچ نہ کیا تو قحط کی تکلیف ناقابل برداشت ہوجائے گی.حضرت یوسفؑ کا تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتانا یوسف علیہ السلام نے غلہ کو جمع کرکے محفوظ رکھنے کا طریق بھی ساتھ ہی بتا دیا ہے جو یہ ہے کہ اگر گندم کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دیا جاوے تو وہ کیڑا وغیرہ لگنے سے زیادہ
Page 457
محفوظ رہتا ہے.تم بھی اسی طرح کرنا.کوئی تعجب نہیں کہ یہ امر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے ہی الفاظ سے اخذ کیا ہو اور یہ خیال کیا ہو کہ گائیں دکھا کر دوبارہ جو بالیں دکھائی ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ غلہ کو بالوں میں ہی رہنے دینا چاہیے.ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ پھر اس کے بعد سات سخت( تنگی کے سال) آئیں گے سوائے اس قلیل مقدار کے جسے تم پس انداز کرلو جو اس( تمام لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ۰۰۴۹ غلہ) کو جوتم نے ان کے لئے پہلے سے جمع کر چھوڑا ہو گا کھا جائیں گے.حلّ لُغَات.اَلشَّدِیْدُ.اَلْبَخِیْلُ.کنجوس اَلْقَوِیُّ.سخت.جَـمْعُہٗ شِدَادٌ.اس کی جمع شِدَادٌ آتی ہے.الشَّدِیْدَۃُ مُؤَنَّثُ الشَّدِیْدِ وَجَمْعُہٗ شَدَائِدُ.شَدِیْدَۃٌ شَدِیْدٌ کی مؤنث ہے اور اس کی جمع شدَائِدُ آتی ہے.پس سَبْعٌ اور شِدَادٌ (یہ دونوں سِنُوْنَ کی جو محذوف ہے نعتیں ہیں) میں سے پہلی صفت اس کے موصوف کے صیغہ واحد کی تانیث کی بناء پر بصیغۂ تانیث لائی گئی ہے اور دوسری صفت اپنے موصوف کے صیغہ کی رعایت سے جو جمع مذکر کا صیغہ ہے بصیغہ مذکر آئی ہے.حَصُنَ حَصُنَ حَصَانۃً مَنُعَ.رک گیا.محفوظ ہو گیا.اَلْمَرْءَ ۃُ حُصْنًا وَحَصَانَۃً کَانَتْ عَفِیْفَۃً.عورت پاکباز رہی.(اقرب) اَحْصَنَ.مَنَعَ.روکا.تفسیر.یعنی اس کے بعد قحط کے دن آئیں گے جن میں پہلا جمع شدہ غلہ سب خرچ ہوجائے گا اور صرف تھوڑا سا جو تم بچا رکھو گے بچے گا.بچا رکھو گے کے الفاظ سے مجبوری پائی جاتی ہے اور غلہ کے بچانے کی مجبوری بیج کی ہی ہوتی ہے.پس مراد یہ ہے کہ بیج کے طور پر جو تم کو جبراً رکھنا پڑے گا وہی رہے گا.باقی سب کھایا جائے گا.یا یہ کہ اس ڈر سے کہ قحط لمبا نہ ہو جائے جو کچھ تم اپنے پیٹ کاٹ کر بچا رکھو گے وہ بچے گا ورنہ سب خرچ ہو جائے گا.
Page 458
ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ فِيْهِ يَعْصِرُوْنَؒ۰۰۵۰ پھر اس کے بعد ایک (ایسا) سال آئے گا جس میں لوگوں کی تنگی دور کی جائے گی اور وہ اس میں (دوسروں کو) عطیے دیں گے.حلّ لُغَات.عَامٌ.اَلْعَامُ السَّنَۃُ.سال ، وَفِی الْمِصْبَاحِ لَا تَفْرُقُ عَوَامُّ النَّاسِ بَیْنَ الْعَامِ وَالسَّنَۃِ اور مصباح میں ہے کہ عوام الناس عَام کے معنوں میں اور سَنَۃ کے معنوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے.وَیَجْعَلُوْنَہُمَا بِمَعْنًی اور ان دونوں کو ہم معنے قرار دیتے ہیں.فَیَقُوْلُوْنَ لِمَنْ سَافَرَ فِیْ وَقَتٍ مِّنَ السَّنَۃِ اَیَّ وَقْتٍ کَانَ الٰی مِثْلِہٖ عَامٌ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سال کے دوران میں اور اس کے کسی حصہ میں سفر کرے اور بارہ مہینے کے بعد واپس آئے تو اس عرصہ کو بھی عَامٌ کہہ دیتے ہیں.وَھُوَ غَلَـطٌ لیکن یہ استعمال صحیح نہیں.اَلسَّنَۃُ مِنْ اَیِّ یَوْمٍ عَدَدْتَہٗ اِلَی مِثْلِہٖ.سَنَۃٌ سے مراد ایک سال کا عرصہ ہوتا ہے.خواہ کسی دن سے شمار کیا جائے.وَالْعَامُ لَایَکُوْنُ اِلَّا شِتَاءً وَصَیْفًا.اور عام سے مراد شمسی سال کے مقررہ مہینوں میں سے پہلے مہینہ کے شروع سے لے کر بارھویں مہینہ کے آخر تک کا عرصہ ہوتا ہے جس کا حساب صیف و شتا کو ملحوظ رکھ کر کیا جاتا ہے.(اقرب) غَاثَ غَاثَ اللہُ الْبِلَادَ یَغِیْثُہَا غَیْثًا: اَنْزَلَ بِھَا الْغَیْثَ اَیْ الْمَطَرَ.اللہ تعالیٰ نے ملک میں بارش نازل کی… وَغَاثَ یَغُوْثُ غَوْثًا.اَعَانَہُ وَنَصَرَہُ.اس کی مدد اور نصرت کی وَاَغَاثَنَا اللہُ بِالْمَطَرِکَشَفَ الشِّدَّۃَ عَنَّابِہٖ.خدا تعالیٰ نے بارش کے ذریعہ سے ہماری تکلیف دور کی.(اقرب) عَصَرَفُلَانًا: اَعْطَاہُ اَلْعَطِیَّۃَ.(اقرب) تفسیر.یُغَاثُ کا لفظ بارش کے لئے مخصوص نہیں اس آیت پر مسیحی مشنری اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مصر کی شادابی کا انحصار بارش پر نہیں بلکہ دریائے نیل کی طغیانی پر ہے لیکن قرآن کریم میں لکھا ہے کہ قحط کے بعد بارش ہوگی اور لوگوں کی تکلیف دور ہوگی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ (نعوذباللہ) قرآن کریم کے نازل کرنے والے کو جغرافیہ کی موٹی باتوں کا بھی علم نہیں.اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں یُغَاثُ النَّاسُ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں اور یُغَاثُ صیغہ مجہول ہے جو غَاثَ یَغِیْثُ سے بھی بن سکتا ہے جس کے معنے بارش نازل کرنے کے ہیں اور غَاثَ یَغُوْثُ سے بھی بن سکتا ہے جس کے معنی مدد کرنے کے ہیں اور اَغَاثَ یَغِیْثُ سے بھی بن سکتا ہے جس کے معنی فریاد کو پہنچنے کے ہیں.اور یُغَاثُ کے تینوں معنے ہوسکتے ہیں.(۱) بارش برسائی جائے گی (۲) مدد کی
Page 459
جائے گی (۳) ان کی فریاد سنی جائے گی اور ان کی تنگی دور کی جائے گی.پس یہ کہنا کہ قرآن کریم نے مصر میں بارش کا ذکر کیا ہے.حالانکہ وہاں بارش نہیں ہوتی.مغالطہ دینا ہے.جب ان الفاظ کے دوسرے معنے موجود ہیں تو کیوں وہ معنے نہ کئے جائیں.ہمارے نزدیک اس آیت میں بارش کی خبر نہیں دی گئی بلکہ یہ بتایا ہے کہ پھر لوگوں کی مدد کی جائے گی یا یہ کہ فریاد سنی جائے گی اور ان کی تنگی دور کردی جائے گی.لفظ یُغَاثُ کے اختیار کرنے میں حکمت اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایسا مشتبہ لفظ استعمال کیوں کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو کوئی اشتباہ ہے ہی نہیں جب عربی میں ایک لفظ ایک خاص معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو قرآن کریم کیوں اس لفظ کو استعمال نہ کرے.دوسرے ہم کہتے ہیں کہ اس دو معنوں والے لفظ کے استعمال میں ایک حکمت تھی اور وہ یہ کہ جیسا کہ بتایا جاچکا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بیان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بھی پیشگوئی تھی اور اس قسم کا قحط آپؐ کے زمانہ میں بھی پڑنے والا تھا لیکن فرق یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں تو اس قحط کا علاج دریا کی طغیانی سے ہونا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بارش کے ساتھ ہونا تھا.پس قرآن کریم نے جس کا ہر لفظ حکمتوں سے پر ہوتا ہے ایسا لفظ استعمال کیا کہ وہ ایک ہی لفظ دونوں زمانوں پر چسپان ہوسکتا ہے.ایک مادہ سے اس کے معنی فریاد سننے اور تنگی دور کرنے کے ہیں اور ان معنوں میں وہ لفظ یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پورا ہوا.دوسرے مادہ سے اس لفظ کے معنی بارش ہونے کے ہیں.ان معنوں سے یہ لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پورا ہوا اور یہ لطیف پیرایۂ کلام قرآن کریم کی عظمت ثابت کرتا ہے نہ کہ اسے قابل اعتراض بناتا ہے.نیل کے ذریعہ سے شاداب ہونا بھی بارش سے ہی وابستہ ہے علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر بارش ہی کے معنے کریں تب بھی کوئی اعتراض نہیں پڑتا کیونکہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ مصر میں بارش ہوگی بلکہ یہ لفظ ہے کہ لوگوں کے لئے بارش نازل کی جائے گی اور اس میں کیا شک ہے کہ گو مصر کی شادابی نیل کی طغیانی پر منحصر ہے نہ کہ بارش پر لیکن نیل کی طغیانی آگے بارش پر منحصر ہے.جو گو مصر میں نہیں ہوتی لیکن ان علاقوں میں تو ہوتی ہے جہاں نیل کا منبع ہے.پس اگر بارش کے معنے لئے جائیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں پڑتا.
Page 460
وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ١ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اور بادشاہ نے (یہ بات سن کر ان سے )کہا (کہ) تم اسے میرے پاس لے آؤ پس جب (بادشاہ کا) پیغام رساں اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ١ؕ اس کے پاس آیا تو اس نے (یعنی یوسفؑ نے اس سے) کہا (کہ) تو اپنے آقا کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ۰۰۵۱ (کہ) جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کی( اس وقت) کیا کیفیت ہے میرا رب ان کے منصوبے کو یقیناً خوب جاننے والا ہے.حلّ لُغَات.بَالٌ.اَلْبَالُ.اَلْحَالُ.حالت کیفیت.اَلْقَلْبُ.دل (اقرب) اَلْبَالُ: اَلْحَالُ الَّتِیْ یُکْتَرَثُ بِھَا.توجہ طلب حالت اور کیفیت…… وَلِذٰلِکَ یُقَالُ مَابَالَیْتُ بِکَذَا بَالۃً اَیْ مَااکْتَرَثْتُ بِہٖ.چنانچہ مَابَالَیْتُ بِکَذَا بَالَۃً کے معنے ہوتے ہیں میں نےفلاں بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور اس کی طرف توجہ نہ کی.قَالَ کَفَّرَ عَنْہُمْ سَیِّئَاتِھِمْ وَاَصْلَحَ بَالَھُمْ.قَالَ فَمَابَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰی اَیْ حَالُہُمْ وَخَبَرُھُمْ اور قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات میں بال کے معنے حال اور خبر ہی کے ہیں.وَیُعَبَّرُ بِالْبَالِ عَنِ الْحَالِ الَّذِیْ یَنْطَوِیْ عَلَیْہِ الْاِنْسَانُ اور بَالَ سے مراد اندرونی اور قلبی کیفیت کے بھی ہوتے ہیں.فَیُقَالُ خَطَرَ کَذَا بِبَالِیْ چنانچہ اسی بنا پر خَطَرَکَذَا بِبَالِیْ کہا جاتا ہے جس کے معنے ہیں فلاں بات میرے دل میں آئی.(مفردات) تفسیر.بادشاہ نے یہ دیکھ کر کہ اس کے ہم مذہب کاہن تو تعبیر کرنے سے رہ گئے اور یوسف علیہ السلام نے ایک نہایت اعلیٰ تعبیر بیان کردی اور مصیبت کا علاج بھی بتا دیا اور اپنے ساقی سے یہ سن کر کہ پہلے بھی ان کی بتائی ہوئی تعبیریں پوری ہوچکی ہیں انہیں قید سے آزاد کرنا چاہا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ وہ اپنی براء ت کرائے بغیر قید سے نکلتے.معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر میں اس وقت نکل آیا تو کسی آئندہ زمانہ میں لوگ میری شکایت بادشاہ سے کردیں گے اور وہ ان امور کو شاید سچا سمجھ لے.اس لئے مناسب ہے کہ ابھی سے سب معاملہ بادشاہ کے سامنے آجائے تاکہ وہ تحقیق کرکے اپنی تسلی کرلے اور آئندہ کسی کو ریشہ دوانی کا موقع نہ ملے.
Page 461
عزیز مصر کی بیوی کی سہیلیوں نے واقعی اپنے ہاتھ کاٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں بھی ہاتھ کاٹنے کا کوئی واقعہ ہوا تھا.یا تو واقعہ میں ان میں سے کسی کا ہاتھ باتیں کرتے زخمی ہو گیا تھا جس کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے اور یا پھر انہوں نے منہ سے کہا ہوگا کہ ہم نے تو اس شخص کو بدنام کرکے اپنے ہاتھ کاٹ لئے ہیں.جسے انہوں نے یاد دلایا ہے.اگر صرف قرآن کریم نے ان کی کیفیت کو ان الفاظ سے ادا کیا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے یہ فقرہ نہیں نکل سکتا تھا.ایک فعل ایک نقطہ نگاہ کی رو سے نیکی ہوتا ہے اور دوسرے نقطہ نگاہ کی رو سے بدی یہاں ایک عجیب نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے جسے لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے اور وہ یہ کہ نیکیاں اور بدیاں بھی مختلف نقطہ ہائے نگاہ کے ماتحت ہوتی ہیں اور بعض دفعہ بالکل متخالف نظر آنے والے معاملات دونوں ہی نیکیاں یا دونوں ہی بدیاں ہوتے ہیں.اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جس فعل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ بھی اسی قسم کے فعلوں میں سے ہے.جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا ہے ان کے لئے دو ہی راستے کھلے تھے یا فوراً نکل آتے یا پہلے برأت کرا کے نکلتے.یہ دونوں فعل بظاہر متضاد ہیں لیکن دو مختلف نقطۂ نگاہ کے رو سے یا تو یہ دونوں فعل نیکی بن جاتے ہیں اور یا دونوں بدی اور وہ اس طرح پر کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام تکبرا ور خودپسندی کے ماتحت ایسا کرتے کہ پہلے لوگ گناہ کا اقرار کریں میں پھر نکلوں گا تو یہ گناہ ہو جاتا.اسی طرح اگر وہ یہ طریق اختیار کرتے کہ اپنے نفس کے آرام کے لئے بغیر کسی دینی فائدہ کے مدنظر رکھنے کے فوراً باہر نکل آتے تو بھی یہ گناہ ہوتا.حضرت یوسفؑ کا نقطہ نگاہ لیکن انہوں نے نکلنے سے انکار کیا نہ اس لئے کہ وہ متکبر تھے بلکہ جیسا کہ انہوں نے خود بتایا ہے محض اس لئے کہ ان کا ایک محسن اس وہم میں مبتلا نہ رہے کہ یوسف (علیہ السلام) نے اس سے غداری کی ہے اور اس اعلیٰ جذبہ کی وجہ سے ان کا یہ فعل ایک اعلیٰ درجہ کی نیکی تھا.آنحضرتؐ کا نقطہ نگاہ مگر ایک چوتھا نقطۂ نگاہ بھی ہے جس کے ماتحت فوراً نکل آنا ایک نیکی بن جاتا ہے اور اس نقطۂ نگاہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے.یہ نقطۂ نگاہ اپنے فرض منصبی کے پورا کرنے کا خیال ہے.ایک نبی یا معلم خدا تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لئے مامور ہوتا ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو اس غرض کے لئے قربان کردے.حتیٰ کہ اگر عزت اور نیک نامی بھی قربان کرنی پڑے تو وہ اس کی پرواہ نہ
Page 462
کرے.ایک نبی اگر قیدخانہ میں ہو تو وہ یا تو تبلیغ نہیں کرسکے گا یا اس کی تبلیغ محدود ہوگی.اگر وہ اس نقطۂ نگاہ سے اپنی آزادی کو دیکھے تو اس کی بہت بڑی قربانی ہوگی.اگر وہ بغیر صفائی کے قید سے نکل آئے اور اپنے کام کے مقابلہ میں اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے.اگر آنحضرت ؐ کو ایسا موقع پیش آتا تو آپ کیا کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے لئے آخری طریق کو پسند کیا ہے.آپؐ فرماتے ہیں کہ لَوْ لَبِثْتُ فِی السِّجْنِ مَالَبِثَ یُوْسفُ لَاَ جَبْتُ الدَّاعِیَ اگر میں اس قدر دیر قید میں رہتا جس قدر یوسفؑ رہے تھے تو میں بلانے والے کی بات کو قبول کرلیتا.(بخاری کتاب التفسیر سورۃ یوسف باب قولہ فلما جاءہ الرسول..) اور مسند احمد حنبل میں ابوہریرہؓ سے ہی روایت ہے لَاَسْرَعْتُ الِاجَابَتَ وَمَا ابْتَغَیْتُ الْعُذْرَ.میں فوراً بات قبول کرلیتا اور یہ عذر نہ کرتا کہ پہلے میری برأت کرو.آنحضرت ؐ کا نقطہ نگاہ بہت اعلیٰ اور بلند ترہے ہر عقلمند انسان سمجھ سکتا ہے کہ دونوں مقامات میں سے وہ مقام زیادہ بلند ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے پسند فرمایا ہے کیونکہ گو عزت کی حفاظت ایک اعلیٰ درجہ کا کام ہے لیکن اگر اس امر کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ تبلیغ کے کام میں ہرج نہ ہو یا اور کسی ایسے کام کے لئے جو قومی یا شرعی یا دینی ہو انسان اپنی عزت کو قربان کردے اور اپنے پر الزام کو رہنے دے تو یہ شخص یقیناً اس شخص سے جو اپنی عزت کی حفاظت کا مطالبہ کسی نیک ارادہ سے کرتا ہے زیادہ اعلیٰ مرتبہ پر ہے.قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ١ؕ قُلْنَ (یہ پیغام سن کر) اس نے (یعنی بادشاہ نے ان عورتوں سے) کہا (کہ) تمہارا (وہ) معاملہ جب کہ تم نے یوسف سے حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ١ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ اس کی مرضی کے خلاف( ایک برا) فعل کروانے کی کوشش کی تھی (اصل میں) کیا تھا انہوں نے کہا (کہ) وہ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ١ٞ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَ اللہ (تعالیٰ) کی خاطر (بدی کے ارتکاب سے) ڈرا تھا (اور) ہم نے اس میں کوئی بھی برائی (کی بات) نہیںمعلوم
Page 463
اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ۰۰۵۲ کی تھی (یہ سن کر) عزیز کی بیوی نے کہا (کہ) اب سچائی بالکل کھل گئی ہے میں نے (ہی) اس سے اس کی مرضی کے خلاف (ایک برا) فعل کرانے کی کوشش کی تھی اور وہ یقیناً راستبازوں میں سے ہے.حلّ لُغَات.خَطْبٌ اَلْخَطْبُ اَلشَّانُ.خاص حالت جو کسی لحاظ سے اہمیت رکھتی ہو.اَلْاَمْرُ صَغُرَ اَوْ عَظُمَ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا.سَبَبُ الْاَمْرِ.وہ بات جس کی وجہ سے یا جس کے لئے کوئی کام یا کوئی معاملہ عمل میں لایا جائے.قَالَ مَاخَطْبُکَ اَیْ مَا شَانُکَ الَّذِیْ تَخْطُبُہُ وَمَا الَّذِیْ حَمَلَکَ علیہِ.چنانچہ جب کسی سے کہیں کہ مَاخَطْبُکَ تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ تم نے کس غرض سے فلاں کام کیا ہے اور کیا بات تمہارے پیش نظر ہے.(اقرب) الخَطْبُ.اَلْحَالُ.حالت.اَلْاَمْرُ الَّذِیْ یَقَعُ فِیْہِ الْمُخَاطَبَۃُ وہ معاملہ جس کے متعلق باہم گفتگو ہو.(تاج) حَصْحَصَ حَصْحَصَ الْحَقُّ.بَانَ بَعدَ کتْـمَانِہ.حق بات جو پہلے مخفی تھی ظاہر ہو گئی اور اصل حقیقت کھل گئی.(اقرب) تفسیر.بادشاہ کو یوسفؑ کی بریت اور عورتوں کی چالاکی کایقینی علم ہو چکا تھا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کو خوابوں کی تعبیر سن کر حضرت یوسفؑ کی پاکیزگی کا اس قدر یقین ہو گیا تھا کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام پر الزام سنا تو تحقیق سے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ الزام غلط ہے.اسی وجہ سے اس نے عورتوں سے سوال کرتے وقت یہ الفاظ استعمال کئے ہیں کہ ’’جب تم نے یوسف کو اس کے منشاء کے خلاف بہکانا چاہا تھا‘‘.پھسلانے کی کوشش میں دوسری عورتیں بھی حصہ دار تھیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں عزیز کی بیوی کی سہیلیاں ہونے کے سبب سے ان عورتوں نے بھی حضرت یوسفؑ کو عزیز کی بیوی کی تائید میں پھسلانا چاہا تھا.کیونکہ بادشاہ کا یہ کہنا کہ تم نے ورغلانا چاہا تھا بتاتا ہے کہ بادشاہ کو ایسی روایت پہنچی تھی مگر یہ یقینی ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل نہیں کرنا چاہا بلکہ عزیز کی بیوی کی طرف مائل کرنا چاہا ہے.ممکن ہے یوں کہا ہو کہ دیکھو یہ تم کو قید کرا دے گی تم اس کی بات مان جاؤ مگر بہرحال جو کچھ انہوں نے کیا وہ عزیز کی بیوی کے لئے کیا کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا بھی علیحدہ ذکر قرآن کریم میں آتا.ضمناً بادشاہ کے منہ سے اس واقعہ کی طرف اشارہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے واقعہ کا حصہ ہی تھا.
Page 464
عزیز کی بیوی کا خودبخود بول کر حضرت یوسف ؑ کی بریت کا اقرار کرنا اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ نے ان عورتوں سے ایسے الفاظ میں بات دریافت کی جن سے وہ سمجھ گئیں کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی بات کو دوسرے کی بات پر مقدم کرتا ہے تو انہوں نے زیادہ اخفاء اپنے مصالح کے خلاف جانا اور حق کو ظاہر کردیا.لیکن جواب ایسا دیا جس سے یوسفؑ کی بریت ظاہر ہو اور عزیز کی بیوی پر بھی کوئی الزام نہ آئے.لیکن اسے خود ہی فکر پڑ گئی اور اسے خیال گزرا کہ اب بات کھل جائے گی اور اب یہ عورتیں میرے قصور کا بھی اظہار کر دیں گی.پس میں خود ہی کیوں نہ اپنے قصور کا اقرار کرلوں تاکہ اگر بادشاہ کا ارادہ سزا دینے کا ہو تو اس سے محفوظ رہوں اس لئے وہ بغیر سوال کرنے کے آپ ہی بول پڑی کہ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ١ٞ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ.اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے حقیقت یہی ہے کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو ان کے منشاء کے خلاف ایک برے فعل کے ارتکاب کی تحریص دلائی تھی.ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ (اور یوسف نے اسے یہ بھی کہا کہ) یہ( بات میں نے) اس لئے (کہی )ہے کہ اس کو( یعنی عزیز کو) علم ہو جائے کہ كَيْدَ الْخَآىِٕنِيْنَ۠۰۰۵۳ میں نے (اس کی)غیر موجودگی میں اس کے حق میں خیانت نہیں کی.اور یہ کہ( میرا ایمان ہے کہ) خیانت کرنے والوں کی( مخالفانہ) تدبیر کو اللہ (تعالیٰ) کامیاب نہیں کرتا.حلّ لُغَات.خَانَ خَانَہٗ فِی کَذَا یَخُوْنُہٗ خَوْنًا وَخِیَانَۃً اُوْتُمِنَ فَلَمْ یَنْصَحْ.امانت میں خیانت کی اَلْعَہْدَنَقَضَہٗ.عہدشکنی کی.یُقَالُ خَانَہُ الْعَہْدَ وَالْاَمَانَۃَ اَیْ فِی الْعَہْدِ وَالْاَمَانَۃِ فَھُوَ خَائِنٌ یعنی خَانَہُ فِی الْعَہْدِ اور خَانَہٗ فِی الْاَمَانَۃِ کی بجائے خَانَہُ الْعَہْدَ اور خَانَہُ الْاَمَانَۃَ بھی بولتے ہیں اور دونوں صورتوں میں معنے ایک ہی رہتے ہیں اور وہ یہ کہ عہد کو توڑا اور امانت میں خیانت کی.(اقرب) ھُدٰی اِنَّ اللّٰہَ لَایَھْدِیْ کَیْدَ الْخَائِنِیْنَ اَیْ لَایَنْفُذُہٗ وَلَا یَصْلِحُہٗ.یعنی اس آیت میں لَایَھْدِیْ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور غدّاروں کی تدبیر اور ان کے منصوبہ کو کامیاب نہیں کرتا.(تاج) اَلضِّلَالُ فَقْدُ مَایُوَصِّلُ اِلَی الْمَطْلُوْبِ.ضِلَالٌ کے معنے ہیں مطلوب چیز تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب کو کھو بیٹھنا اور اس بنا پر اس کو نہ پاسکنا.وَتُضَادُہُ الْھِدَایَۃُ اور ہَدَایۃٌ اس کی ضد ہے.پس ہدایت کے معنے ہیں
Page 465
مطلوب چیز تک پہنچنے اور اسے پانے کے یعنے تمام اسباب اور ذرائع کا میسر آجانا اور ان کا مطلوب چیز تک پہنچا دینا.یعنی کامیاب کرنا.(تاج) تفسیر.ذٰلِکَ لِیَعْلَمَ حضرت یوسف کا قول ہے یا عزیز کی بیوی کا اس قول کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ کس کا ہے.بعض کہتے ہیں کہ عزیز کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے غیبت میں یوسفؑ کی خیانت نہیں کی.لیکن یہ فقرہ اس کے منہ سے بہت بھدا معلوم ہوتا ہے کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اس نے خیانت کی ہے.پس میرے نزدیک انہی لوگوں کا قول درست ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قول حضرت یوسفؑ کا ہے اور مراد یہ ہے کہ میں نے بادشاہ کو دھوکا نہیں دیا.یعنی کسی نہ کسی دن یہ امر بادشاہ کے سامنے آنا تھا.اس وقت اسے یہ خیال ہوسکتا تھا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسے امر کو پوشیدہ رکھ کر عہدہ لے لیا اس وجہ سے میں نے اس کا ازالہ کر دیا ہے.اب کبھی بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بادشاہ کو اصل حالات سے ناواقف رکھ کر دھوکا دیا ہے.لِیَعْلَمَ کا فاعل کون ہے؟ یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ یَعْلَمُ کی ضمیر کو عزیز کی طرف پھیرا جائے اور مراد یہ لی جائے کہ عزیز یہ خیال نہ کرے کہ میں نے اس کی خیانت کی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یَعْلَمُ کی ضمیر بادشاہ کی طرف جاتی ہو اور لَمْ اَخُنْہُ کی ضمیر عزیز کی طرف اور مراد یہ ہو کہ بادشاہ جان لے کہ میں نے اپنے محسن عزیز کی خیانت نہیں کی تھی تاکہ آئندہ اسے شبہ نہ پیدا ہو کہ جس طرح اس محسن کی خیانت کی تھی ممکن ہے یہ میرا بھی خائن ہو.حضرت یوسفؑ نے اپنے امین ہونے کا اظہار کیوں کیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ وہ فلاں کام پر مامور کئے جائیں گے.اس لئے آپ نے یہ برأت پہلے کرالی کہ آپ خائن نہیں ہیں تاکہ آئندہ آپ کے کام پر کوئی الزام نہ ہو.اس آیت میں ہر ایک خائن کے اپنی خیانت میں ناکام رہنے کا ذکر نہیں آخری حصہ آیت سے یہ مراد ہے کہ ایسے خائن جو ان لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خاص کام لینا چاہتا ہے اور اَلْ جو خَائِنِیْنَ کے اوپر ہے ال عہد ذکری کا ہے یعنی جن کا ذکر پہلے ہوا ہے اور پہلے ذکر ایسے خائنوں کا ہوا ہے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے مقابلہ میں خیانت کی ہے جنہیں ایک خاص کام پر مقرر کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا.پس یہ مراد نہیں کہ کوئی خائن اپنی خیانت میں کامیاب ہی نہیں ہوتا.کئی لوگ خیانت کرتے ہیں اور اس دنیا میں ان کی خیانت چھپی رہتی ہے لیکن ایسے خائن کی خیانت کو اللہ تعالیٰ کبھی چھپا نہیں رہنے دیتا جو اس کے ماموروں کے مقابلہ میں خیانت کرتے ہیں.
Page 466
حضرت یوسفؑ کا بیان کہ اگر میں خائن ہوتا تو میری یہ نصرت و تائید الٰہی نہ ہوتی اس آیت سے یہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خائنوں کی نصرت نہیں کرتا اور چونکہ یوسفؑ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تھی کہ پہلے بادشاہ کے دو خاص خدام کو خوابیں دکھائیں پھر خود بادشاہ کو خواب دکھائی پس وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا میری مدد کرنا بلاوجہ نہ تھا بلکہ میں حق پر تھا اس لئے وہ میری مدد کررہا تھا.وَ مَاۤ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ١ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا اور میں اپنے نفس کو (ہر قسم کی غلطی سے) بری قرار نہیں دیتا کیونکہ( انسانی) نفس سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم رَحِمَ رَبِّيْ١ؕ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰۰۵۴ کرےبری باتوں کا حکم دینے پر بہت دلیر ہے.میرا رب( کمزوریوں پر) بہت پردہ ڈالنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.اَمَّارَۃٌ : اَمَّارَۃٌ امر سے بنا ہے اور یہ مبالغہ کا مؤنث کا صیغہ ہے.مذکر کا صیغہ اَمَّارٌ ہے جس کے معنے ہیں اَلْکَثِیْرُ الْاَمْرِ.بہت حکم دینے والا.وَالْمُغْرِیْ کسی کام کے کرنے کے لئے اکسانے والا.چونکہ نفس عربی میں مؤنث ہے اس لئے اَمَّارَہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے.السُّوْءُ: کُلَّ مَا یَغُمُّ الْاِنْسَانَ مِنَ الْاُمُوْرِ الدُّنْیَوِیَّۃِ والْاُخْرَوِیَّۃِ وَمِنَ الْاَحْوَالِ النَّفْسِیَّۃِ وَالْبَدَنِیَّۃِ وَالْخَارِجَۃِ مِنْ فَوَاتِ مَالٍ وَجَاہٍ وَفَقْدِ حَمِیْمٍ.دنیوی و اخروی معاملات اور نفسی و بدنی حالات یا ان کے علاوہ اور خارجی واقعات یعنی مال و عزت کے کھوئے جانے یا دوست و احباب کی علیحدگی کی وجہ سے جو امور انسان کو اندوہ گین بنائیں ان سب کو سُوء کے نام سے موسوم کرتے ہیں.(مفردات) تفسیر.نبی کی فطرت پاکیزہ ہوتی ہے نبی کی فطرت بھی کیا ہی پاکیزہ ہوتی ہے.حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری یہ غرض نہ تھی کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں پاک ہوں بلکہ میں ایک تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور کبھی وہ ان خائنوں کی تدابیر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا جو اس کے ماموروں کے مقابل پر کھڑے ہوتے ہیں.یوسفؑ کو اپنی برأت میں اپنی بڑائی مطلوب نہ تھی پس میں نے جو کچھ تدبیر کی ہے اپنی بڑائی کے اظہار
Page 467
کے لئے نہیں کی.بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اظہار کے لئے کی ہے.دوسرے میں نے اس لئے برأت کی کوشش کی ہے کہ تا بتاؤں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے انہیں کوئی شخص بدی میں نہیں ڈال سکتا ورنہ اپنے نفس کی بڑائی کی خاطر میں نے یہ کام نہیں کیا.نیّر الہام ہی نفس کو صحیح راستہ پر چلاتا ہے بلکہ مجھے تو اقرار ہے کہ نفس انسانی بغیر اللہ تعالیٰ کے رحم کے یعنی شریعت اور ہدایت اور فضل کے کچھ بھی نہیں کرسکتا.بلکہ پے درپے بری باتوں کا حکم دیتا چلا جاتا ہے کیونکہ نیّرِ الہام ہی ہے جو اسے صحیح راستہ پر چلاتا ہے.الَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ سے مراد کلام الٰہی ہے قرآن کریم نے دوسری جگہ پر بتلایا ہے کہ اَلرَّحْمٰنُ.عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ.(الرحمٰن:۲)رحمانیت سے ہی کلام الٰہی کا نزول ہوتا ہے.پس اِلَّامَارَحِمَ رَبِّیْ سے مراد وہی رحمت ہے یعنی کلام الٰہی.بغیر اس کے انسانی فطرت ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو خطرناک تاریکی میں پہاڑ کی چوٹیوں پر سے گزر رہا ہو.کیونکہ باوجود آنکھوں کے ہر وقت خطرہ ہی ہوتا ہے اور بار بار غلطیاں کرتا ہے.جب الہام کا سورج چڑھتا ہے تبھی روحانی آنکھ بھی کام دیتی ہے.نفس کی تین حالتیں دوسری جگہ قرآن کریم نے نفس کی دواور حالتیں بتلائی ہیں.لَوَّامَۃ ایک نفس لوامہ.جیسا کہ فرماتا ہےوَ لَاۤ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ( القیامۃ:۳) مُطْمَئِنَّۃ اور دوسری نفس مُطْمَئِنَّہ جیسے کہ فرماتا ہےيٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ.ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.(الفجر:۲۸،۲۹) نفس امارہ سے مراد پس اس جگہ نفس سے مراد وہ ابتدائی حالت ہے جبکہ الہام سے نفس کو ناآشنائی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وہ وارث نہیں ہوتا.ورنہ یہ مراد نہیں کہ انسانی نفس ہمیشہ بدی کی تعلیم دیتا ہے.اس کا رد خود اس آیت میںاِلَّا مَارَحِمَ رَبِّیْ کہہ کر کردیا ہے.انسان اپنی ذات میں گنہ گار پیدا نہیں ہوا اور نہ یہ مراد ہے کہ انسان اپنی ذات میں گنہگار پیدا ہوتا ہے.کیونکہ اس جگہ پیدائش کا ذکر نہیں ہے.بلکہ دنیاوی آلائشوں کا شکار ہونے کے بعد جو اس کی حالت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے.ورنہ پیدائش کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ’’ وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰھَا‘‘(الشمس:۸) ہم نفس کی قسم کھاتے ہیں اور اس کی اس حالت کمال کی جو ہم نے پیدا کی ہے.نفس کو اللہ تعالیٰ نے پاک حالت میں کیا ہے پس نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے پاک حالت میں پیدا کیا
Page 468
ہے.آگے وہ باہر آکر دوسروں کے اثر سے ناپاک ہوتا ہے.یا جو اسے ناپاک نہ ہونے دے اس کو پاک رکھتا ہے.غرض اس جگہ نفس کی پیدائش کی حالت کا ذکر نہیں ہےبلکہ دنیوی آلائشوں سے ملوث ہونے کے بعد کا ذکر ہے.اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ کے تین معنی اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْکے ایک تو یہ معنی ہیں کہ اِلَّا النَّفْسَ الّتِیْ رَحِمَھَا رَبِّیْ فَاِنَّھَا لَاتَأْمُرُ بِالسُّوْءِ یعنی وہ نفس جس پر خدا رحم کردے یعنی نفس مطمئنہ وہ بدی کا حکم نہیں کرتا.دوسرے یہ کہ مَامَنْ کی جگہ استعمال ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ اِلَّا الَّذِیْ رَحِمَہٗ رَبِّیْ سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم کرے.باقی لوگ نفس امارہ کے حملہ کا شکار ہوتے رہتے ہیں.پس جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے وہ اپنے نفس کی بات نہیں مانتے.تینوں معنے مختلف درجوں کے لوگوں کے لحاظ سے ہیں تیسرے یہ کہ یہ استثناء منقطع ہے اور ما مصدریہ ہے اور معنے یہ ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت جسے چاہے بچا لے.یہ تینوں معنے مختلف درجوں کے لوگوں کے لحاظ سے ہیں.یعنی (۱) بعض نفس پاک ہوجاتے ہیں اور وہ برائی کا حکم ہی نہیں دیتے.یہ اعلیٰ درجہ کے ہیں.(۲) اس سے ادنیٰ درجہ کے لوگ وہ ہیں کہ ان کا نفس تو بدی کا حکم دیتا ہے لیکن وہ نفس سے مغلوب نہیں ہوتے.یہ درمیانی درجہ کے ہیں.(۳) اس سے ادنیٰ درجہ کے لوگ وہ ہیں کہ اپنے نفس امارہ سے مغلوب ہوجاتے ہیں.مگر خداوند تعالیٰ کی رحمت ان کو بچادیتی ہے اور انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے.اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌکہنے کی وجہ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میں تو غفور رحیم رب کا بندہ ہوں اس لئے میرا بھی یہی فرض تھا کہ دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالتا لیکن یہاں چونکہ سوال خدا تعالیٰ کی عزت کا تھا اس لئے میں خاموش نہیں رہا.
Page 469
وَ قَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖۤ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ١ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے( یعنی یوسف کو) میرے پاس لاؤ.(تاکہ) میں اسے اپنے (خاص کاموں کے) لئے قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ۰۰۵۵ منتخب کر لوں(جب یوسفؑ آئے اور) جونہی اس نے (یعنی بادشاہ نے) اس سے بات چیت کی (تو ان کو ہر طرح قابل پا کر یوں) بولا کہ تو آج (سے) ہمارے ہاں معزز مرتبہ والا (اور ہر طرح سے) اعتباری آدمی( شمار) ہو گا.حلّ لُغَات.اِسْتَخْلَصَ: اِسْتَخْلَصَ الرَّجُلَ اخْتَصَّہُ بِدُخْلُلِہِ.کسی کو اس کی باطنی صفائی کی وجہ سے خاص کرلیا.وَالشَّیءَ اِخْتَارَہُ.کسی چیز کو منتخب کرلیا.چن لیا.(اقرب) مَکِیْنٌ: مَکُنَ فُلَانٌ عِنْدَالسُّلْطَانِ مَکَانَۃً عَظُمَ عِنْدَہُ وَارتَفَعَ وَصَارَذَا مَنْزِلَۃٍ.بادشاہ کے ہاں صاحبِ قدر و منزلت ہو گیا اور ایسے انسان کو مکین کہتے ہیں.اس کی جمع مکناء ہے.(اقرب) تفسیر.بادشاہ کی عزیز مصر کو ایک لطیف سرزنش بادشاہ نے اس فقرہ سے ایک لطیف سرزنش عزیز کو جس کے پاس یوسف علیہ السلام رہے کی ہے اور بتایا ہے کہ ایسے شخص کی تم قدر نہیں کرسکے.اب میں اسے خود اپنے قرب میں جگہ دے کر قدر کروں گا.یہ تو ملاقات سے پہلے کی حالت تھی.جب ملاقات کی تو یوسف علیہ السلام کا اور بھی گرویدہ ہو گیا ور کہا آپ کو میرے دربار میں خاص منزلت ملے گی اور امین کہہ کر بتایا ہے کہ میں آپ پر شبہ نہیں کروں گا اور آپ پر پوری طرح اعتبار کروں گا.بادشاہ کے ہاں حضرت یوسفؑ کا تقرب بائبل میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا سوائے تاج کے اور سب کچھ تجھ کو دوں گا اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنی سواری کے بعد جو دوسرے درجہ کی سواری تھی وہ حضرت یوسفؑ کو سواری کے لئے دی بلکہ شہر میں اعلان کرایا کہ میرے حکم کے بعد دوسرے درجہ پر حکومت اس شخص کی ہوگی.
Page 470
قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآىِٕنِ الْاَرْضِ١ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ۰۰۵۶ (اس پر یوسفؑ نے) کہا کہ مجھے (تو) ملک کے خزانوں پر( افسر) مقرر کر دیں کیونکہ میں یقیناً (خزانوں کی) بہترین حفاظت کرنے والا اور( ان کے خرچ کے وجوہ کو) خوب سمجھنے والا ہوں.تفسیر.حضرت یوسفؑ کی خزائن پرمتصرف ہونے کی خواہش کی وجہ انہوں نے سمجھا کہ اگر وزیر ہو گیا تو روز کے جھگڑے پڑے رہیں گے.دوسرے اس لئے کہ اگر خزائن پر کوئی اور مقرر ہوا تو ممکن ہے کہ وہ حسد سے کام بگاڑ دے اور پھر الزام مجھ پر آئےکہ اس نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ غلط نکلی اس لئے اپنے ہاتھ میں اس انتظام کو لینا چاہا.سکیم کے تیار کرنے والے کے سپرد کام کیا جائے حضرت یوسفؑ کی اس خواہش سے ایک نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جو شخص کسی کام کی سکیم تیار کرے اگر وہ اس کام کے قابل ہو تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ کام اس کے سپرد کیا جائے.حضرت یوسفؑ کے عہدہ مانگنے کے متعلق اعتراض کا جواب بعض لوگ اس جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ عہدہ مانگنا نہیں چاہیے پھر حضرت یوسفؑ نے ایسا کیوں کیا.اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دراصل عہدہ مانگا نہیں بلکہ اس سوال سے انہوں نے اپنا عہدہ گرایا ہے کیونکہ بادشاہ تو انہیں وزارت عظمیٰ کے عہدہ پر مقرر کرنے لگا تھا اور وہ قحط کے کام کا مطالبہ کرتے ہیں.وَ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْاَرْضِ١ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ اور اس طرح (مناسب حالات پیدا کر کے) ہم نے یوسفؑ کو (اس) ملک میں ایک بااختیار عہدہ عطا کیا.وہ( اپنی يَشَآءُ١ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَ لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مرضی کےمطابق )جہاں (کہیں) چاہتا ٹھہرتا.ہم جسے چاہتے ہیں (اس دنیا میں ہی) اپنی رحمت سے( حصہ) الْمُحْسِنِيْنَ۰۰۵۷ دیتے ہیں اور ہم نیکو کاروں کااجر ضائع نہیں کیا کرتے.حل لغات.یَتَبَوَّاُ تَبَوَّأَ سے مضارع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے معنے کسی جگہ کو اپنی جائے رہائش
Page 471
بناکر اس میں ٹھہرنے کے ہیں.مزید تشریح کے لئے دیکھئے یونس ۸۵.اَلْاَجْرُ اَلثَّوَابُ.اجر کے معنے ہیں ثواب بدلہ (اقرب) اَلْاَجْرُ.والاُجْرَۃُ مَایَعُوْدُ مِنْ ثَوَابِ الْعَمَلِ دُنْیَوِیًّا کَانَ اَوْ اُخْرَوِیًّا.دنیوی یا اخروی کام کے بدلہ میں جو کچھ ملے اس کو اجر اور اجرت کہتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِوَ اٰتَیْنَاہُ اَجْرَہٗ فِی الدُّنْیَا.(مفردات) تفسیر.مکّنَّا کے بلحاظ مقام کے دو مختلف معنی یہاں بھی مکّنّا فرمایا اور پہلے بھی لیکن وہاں اس کے ساتھ وَلِنُعَلِّمَہٗ مِنْ تَأْوِیْلِ الْاَحَادِیْثِ فرمایا تھا کہ ابھی ہم نے اس پر مصائب و مشکلات ڈال کر امتحان لینا ہے اور یہاںنُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ فرما کر بتایا ہے کہ ابتلاء کا زمانہ گزر گیا.اب ہم نے اسے ایسی عزت دی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور ان پر رحمت ہی رہے گی.وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ جو شخص دنیا میں محسن ہوتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا.محسن سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ؎ (الرعد:۱۸) لیکن خصوصاً محسن سے وہ شخص مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو اور اس سے خاص تعلق رکھنے والا ہو.حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو حضورؐ نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی عبادت پورے طور پر بجالائے.احسان کےمعنے پورے طور پر عبادت بجا لانے کے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص کے سوال پر کہ مَا الْاِحْسَانُ احسان کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اَنْ تَعْبُدَاللہَ کَاَنَّکَ تَرَاہُ فَاِنْ لَّمْ تَکُنْ تَرَاہُ فَاِنّہٗ یَرٰکَ.( بخاری کتاب الایمان باب سؤال جبرئیل النبی عن الایمان والاسلام و غیرھا) محسن وہ ہے جو ایسے رنگ میں عبادت کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مرتبہ اسے حاصل نہ ہو تو کم سے کم اسے یہ نظر آئے کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے.آنحضرت صلعم کی حضرت یوسفؑ سے چودھویں مشابہت حضرت یوسف کی طرح آنحضرت ؐ بھی نکالے جانے کے بعد عزت پاگئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس بارہ میں بھی مشابہت ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گھر سے اس حسد سے نکالا تھا کہ بڑا ہونے کی خوابیں دیکھتا ہے اسے یہاں سے نکال دیں تو یہ ذلیل ہو جائے گا.اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے.وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے.
Page 472
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی آپؐ کو اس نیت سے نکالا تھا لیکن جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اس جگہ جہاں وہ جاکر بسے خدا تعالیٰ نے خاص عزت دی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بجائے ذلت کے خاص عزت ملی.آنحضرتؐ اور حضرت یوسفؑ میںفرق صرف فرق یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی عزت نیابتی اور بادشاہ کی طرف سے تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزاد حکومت عطا فرمائی اور خود بادشاہ بنا دیا اور یہی فرق ان دونوں وجودوں میں روحانیت کے لحاظ سے بھی تھا.وَ لَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَؒ۰۰۵۸ اور( اس دنیاوی اجر کے علاوہ) آئندہ (زندگی کا) بدلہ ایمان لانے والوں اور( اللہ تعالیٰ کا) تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے( کہیں) بڑھ (چڑھ) کرہوگا.تفسیر.اولیاء اور انبیاء ذلیل نہیں ہوتے یعنی دنیا میں بھی ہم ان کواجر دیتے ہیں لیکن صرف یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ اولیاء و انبیاء ذلیل نہیں ہوتے.ہاں اصل اجر ان کا آخرت میں ہی ہے جو سب قسم کی نعمتوں سے بہتر ہے.وَ جَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهٗ اور( اس قحط کے زمانہ میں) یوسفؑ کے بھائی (بھی اس ملک میں) آئے پھر (وہ) اس کے حضور میں حاضر (بھی) مُنْكِرُوْنَ۰۰۵۹ ہوئے اور اس نے انہیں(دیکھتے ہی) پہچان لیا.مگر وہ اسے نہ پہچان سکے.حلّ لُغَات.دَخَل دَخَلَ الْبَیْتَ ضِدُّ خَرَجَ دخل کے معنی ہیں اندر آیا.دَخَلَ عَلٰی فُلَانٍ: زَارَہٗ.اس سے ملا.(اقرب) پس دَخَلُوْا عَلَیْہِ کے یہ معنے ہوئے کہ وہ اس کے پاس گئے یا وہ اس کے حضور حاضر ہوئے.مُنْکِرُوْن اَنْکَرَہٗ جَھِلَہٗ.اَنْکَرَ کے معنے ہیں اسے نہ پہچانا.ا س سے بے خبر رہا.اس سے اسم فاعل کا صیغہ
Page 473
مُنْکِرٌ بنتا ہے اور مُنْکِرُوْنَ اس کی جمع ہے وَھُمْ لَہٗ مُنْکِرُوْنَ کے معنے ہوئے کہ وہ اسے نہ پہچان سکے.تفسیر.مفسرین نے اس جگہ بہت بحث کی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے داڑھی آگئی تھی اور آپ موٹے ہو گئے تھے اس لئے ان کے بھائی انہیں نہ پہچان سکے.اگر ایسا ہی ہوا ہوتا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کا قرآن شریف میں ذکر کیا جاتا.میرے نزدیک اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے شروع میں کہی تھی کہيَـخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ.ان کا خیال تھا کہ جب یوسفؑ باپ کے پاس نہ رہے گا تو ہماری عزت بڑھ جائے گی.حضرت یوسفؑ کے بھائی انہیں ان کی ترقی کے باعث نہ پہچان سکے سو اس آیت میں بتایا ہے کہ حضرت یوسفؑ تو اس جدائی کے سلسلہ میں اس قدر ترقی کر گئے کہ ان کے بھائی انہیں پہچان ہی نہ سکے لیکن وہ ویسے کے ویسے ہی رہے.آنحضرت صلعم کی حضرت یوسفؑ سے پندرھویں مشابہت آنحضرتؐ کی حیرت انگیز ترقی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس بات میں بھی مشابہت ہے کہ آپ کے بھائی بھی آپ کی ترقی کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے تھے.آنحضرت صلعم کا ہرقل کے نام خط جب آپؐ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور اسی سلسلہ میں ایک خط روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا.گو اس وقت ابوسفیان ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام میں گیا ہوا تھا ہرقل یہ خط پڑھ کر گھبرا گیا.اس نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو اس جرأت سے مجھے خطاب کرتا ہے.لوگوں نے کہا کہ یہ عرب کا ایک شخص ہے جو نبوت کا مدعی ہے.اس نے کہا کہ ہمیں اس کے حالات دریافت کرنے چاہئیں.چنانچہ ابوسفیان اور اس کے ہمراہیوں کو دربار میں حاضر کیا گیااور ہرقل نے یہ معلوم کرکے کہ ابوسفیان سب کا سردار ہے اس سے سوالات کرنے شروع کئے اور اس کے ساتھیوں کو کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم فوراً بتلا دینا.ہرقل کے ابو سفیان سے سوالات پھر اس نے ابوسفیان سے چند سوال کئے جو آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لئے ایک زبردست نشان کے طو رپر قائم ہیں.اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس طرح سے جرح کی ہے کہ دیکھ کر حیرت آتی ہے.پہلا سوال مثلاً اس نے پوچھا کہ اس کے باپ دادوں سے کوئی بادشاہ تھا.کیونکہ ایسا ہو تو سمجھا جائے گا کہ وہ گم شدہ حکومت و عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے.ابوسفیان نے کہا کہ نہیں.
Page 474
دوسرا سوال اس نے پوچھا کیا وہ اس دعویٰ سے پہلے کبھی جھوٹ بولتا تھا.ابوسفیان نے کہا کہ نہیں.تیسرا سوال.پھر اس نے کہا کیا اس نے کبھی معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے.ابوسفیان نے کہا کہ نہیں.مگر حال میں ہی اس کا ایک معاہدہ ہمارے ساتھ ہوا ہے معلوم نہیں وہ اس کے متعلق کیا کرے گا.ا بوسفیان کہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ جو بات آپؐ کے خلاف کرسکا وہ یہی تھی.کیونکہ میںڈرتا تھا کہ میرے ساتھی جھٹلا نہ دیں.چوتھا سوال پھر اس نے پوچھا کہ اسے بڑے لوگ مانتے ہیں یا چھوٹے.ابوسفیان نے کہا کہ چھوٹے.اسی طرح کی بہت سی باتیں ہوئیں اور آخر ہرقل نے کہا کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو وہ ضرور اس علاقہ کا حاکم ہو جائے گا.جہاں میں اس وقت ہوں.آنحضرت ؐ کے متعلق پہلی کتب میں شام کو فتح کرنے کی پیشگوئی تھی کیونکہ پہلی کتب میں یہ پیشگوئی تھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شام کو فتح کریں گے اور شاہ روم اس وقت شام میں تھا.اس کے اس فقرہ سے درباریوں میں شور پڑ گیا اور ابوسفیان گھبرا کر باہر نکلا اور نہایت تعجب سے کہا لَقَدْاَمِرَاَمْرُ ابْنِ اَبِیْ کَبْشَۃ (بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ )کہ ہم نے تو پہچانا ہی نہیں.محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عزت تو بہت بڑھ گئی ہے اور اس کا کام بہت ترقی کر گیا ہے.آنحضرت ؐ کو ابن ابی کبشہ پکارنے کی وجہ (مکہ والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیر کے طور پر ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے ابو کبشہ قبیلہ خزاعہ میں سے ایک شخص تھا جس نے بت پرستی چھوڑ کر ستارہ پرستی شروع کردی تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہنے سے مکہ والوں کی مراد یہ تھی کہ جس طرح ابوکبشہ نے آبائی دین کو چھوڑ دیا تھا اسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے اس لئے یہ گویا اس کا روحانی بیٹا ہے) غرض وہاں آکر ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں ورنہ مکہ میں وہ آپ کی حیثیت نہیں جانتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حقیقت معلوم تھی.وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اور جب اس نے انہیں ان کا سامان دے کر( واپسی کے لئے) تیار کیا تو( ان سے) کہا (کہ) تمہارے باپ کی اَبِيْكُمْ١ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْۤ اُوْفِي الْكَيْلَ وَ اَنَا خَيْرُ طرف سے جوتمہارا ایک بھائی ہے( اب کے) اسے( بھی اپنے ساتھ) میرے پاس لانا کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں
Page 475
الْمُنْزِلِيْنَ۰۰۶۰فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ ماپ پورا دیتا ہوں اور (نیز)میں مہمان نوازوں میں سے بہترین (مہمان نواز) ہوں.اور اگر تم اسے میرے پاس وَ لَا تَقْرَبُوْنِ۰۰۶۱ نہ لائے تو میرے پاس تمہارےلئے کوئی( غلہ) بھی ماپ (کر دینے کے لئے )نہیں ہو گا اور نہ تم میرے پاس آنا.حلّ لُغَات.جَھَّزَھُمْ.جَہَّزَ الْقَوْمَ تَجْھِیْزًا.اِذَا تَکَلّفَ لَھُمْ بِجَھَازِھِمْ لِلسَّفَرِ.جَھَّزَالْقَوْمَ کے معنے ہیں جانے والوں کو پرتکلف طور پر سامان دے کر رخصت کیا.تَجْھِیْزُ الْغَازِیْ.تَحْمِیْلُہٗ وَاِعْدَادُ مَا یَحْتَاجُ اِلَیْہِ فِیْ غَزْوِہِ.جب غازی کے لئے تجہیز کا لفظ آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں سپاہی کو سواری اور آلات جنگ وغیرہ دے کر میدان جنگ میں بھیجنا.جَھَازٌ وَجَھَازُ الْمَیِّتِ وَالْعَرُوْسِ وَالمُسَافِرِ مَایَحْتَاجُوْنَ اِلَیْہِ.اور جَھَازٌ اس سامان کو کہتے ہیں جو دلہن یا مسافر کو رخصت کرتے وقت دیا جاتا ہے یا وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے یا کفن جس میں میت کو لپیٹ کر اسے دفن کیا جاتاہے.(تاج) اَلْکَیْلُ: کَالَ الطَّعَامَ کَیْلًا وَاکْتَالَہُ بمعنًی کَیْلٌ کَالَ میں سے ہے اور کَالَ اور اِکْتَالَ دونوں کے معنے ہیں.ماپا.اِکْتَالُوْا عَلَی النَّاسِ اَیْ مِنْہُمْ لِاَنْفُسِھِمْ قَالَ ثَعْلَبٌ مَعْنَاہُ مِنَ النَّاسِ.یعنی آیت اِکْتَالُوْا عَلَی النَّاسِ میں علٰی کے معنے لینے کے اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اس جگہ لینے کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے.ثَعلب امامِ لغت و دیگر محققین کا اختلاف چنانچہ ثعلب امام لغت کا یہی قول ہے وَقَالَ غَیْرُہُ اکتلتُ عَلَیْہِ اَخَذْتُ مِنْہُ اور باقی محققین لغت کہتے ہیں کہ یہ معنی علیٰ کی وجہ سے نہیں.اِکْتَالَ کے معنی ہی یہی ہیں اور اس کا صلہ علیٰ ہوتا ہے.یُقَالُ کَالَ الْمُعْطِیْ وَاکْتَالَ الْاٰخِذُ.کَالَ کا لفظ ماپ کر دینے کے لئے مخصوص ہے.اور اِکْتَالَ کا لفظ لینے کے لئے.کَالَہٗ طَعَامًا وَکَالَ لَہٗ بِمَعْنًی اور کَالَ بغیر صلہ کے بھی متعدی ہوتا ہے اور صلہ لام کے ساتھ بھی.اور دونوں صورتوں میں معنے ایک ہی ہوتے ہیں.یعنی ماپ کر دیا.وَالْکَیْلُ وَالْمِکْیَلُ مَاکِیْلَ بِہٖ حَدِیْدًا کَانَ اَوْخَشَبًا اور کَیْل کے ایک معنے لفظ مِکْیَلٌ کی طرح ماپنے کے آلہ کے بھی ہیں خواہ لوہے کا ہو یا لکڑی کا.وَکَالَ الدَّرَاھِمَ وَ زَنَھَا سکوں کے ساتھ یہ لفظ آئے تو اس کے معنے وزن کرنے کے ہوتے ہیں.کُلُّ
Page 476
مَا وُزِنَ فَقَدْ کِیْلَ وزن کرنے کا دوسرا نام کیل بھی ہے.اس لئے ہر تولنے کی چیز کے لئے وزن کی بجائے کیل کا لفظ استعمال ہوسکتا ہے.(تاج) تفسیر.بائبل حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کو جاسوس قرار دیتی ہے بائبل کہتی ہے کہ حضرت یوسفؑ نے انہیں کہا ’’اور اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ.تب میں مانوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے ہو.‘‘ (پیدائش باب ۴۲ آیت ۳۴ )یعنی انہیں جاسوس قرار دیا.گویا انہیں ڈرایا.قرآن شریف کا بائبل کے بیان سے اختلاف لیکن اس کے بالمقابل قرآن شریف محبت کا پہلو پیش کرتا ہے یعنی حضرت یوسفؑ نے ان کے ساتھ ملاطفت کا سلوک کیا.جس سے ان کے دلوں میں آئندہ خود آنے اور بھائی کو لانے کی رغبت پیدا ہو.ممکن ہے کہ حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں کو پہچان کر حضرت یعقوبؑ اور دیگر خاندان کے افراد کے متعلق بہت سوالات کئے ہوں اور اس طرح کرید کرید کر پوچھنے سے ان کے بھائیوں کو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہو کہ حضرت یوسفؑ انہیں جاسوس سمجھ رہے ہیں.ورنہ ایک نبی کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ ان کو پہچانتا ہوا انہیں جاسوس قرار دے.یہ توا یک قسم کا جھوٹ بن جاتا ہے.بائبل کی ٹھوکر کی وجہ پس میرے نزدیک بائبل نے بھائیوں کے خیال کو نقل کر دیا ہے اور حقیقت بیان نہیں کی اور یوں بھی بھائی کے نہ لانے کو جاسوسی کا ثبوت قرار دینا بہت بودی اور کچی دلیل ہے اور کوئی عقلمند ایسی بات نہیں کرسکتا.قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَ اِنَّا لَفٰعِلُوْنَ۰۰۶۲ انہوں نے کہا ہم ضرور اس کے متعلق اس کے باپ کو پھسلانے کی کوشش کریں گے اور ہم یقیناً یقیناً ّ(یہ کام) کر کے رہیں گے.حلّ لُغَات.سَنُرَاوِدُ سَنُرَاوِدُ عَنْہُ اَبَاہُ رَاوَدَ سے مضارع متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ہم ضرور اس کے متعلق اس کے باپ کو پھسلانے کی کوشش کریں گے.مزید تشریح کے لئے دیکھیں سورۃ یوسف آیت۲۴.تفسیر.ایک گناہ کے نتیجہ میں دوسرا گناہ پیدا ہوتا ہے ایک گناہ کے نتیجہ میں دوسرا گناہ پیدا ہوتا ہے.جب برادران یوسف نے گناہ کا طریق اختیار کیا تو خیالات گناہ سے ملوث ہو گئے اور اب ان کا طریق
Page 477
کلام بھی قابل اعتراض ہوگیا وہ کس گستاخی سے کہتے ہیں کہ ہم اس کے باپ کو ورغلا کر اسے لے آئیں گے.گویا ایک طرف اس کو اپنا باپ نہیں قرار دیتے اور دوسری طرف اسے بے وقوف بنانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں.وَ قَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی (واپس) ان کے بوروں میں رکھ دو.شائد جب وہ لوٹ کر اپنے يَعْرِفُوْنَهَاۤ۠ اِذَا انْقَلَبُوْۤا اِلٰۤى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ۰۰۶۳ گھروالوں کے پاس جائیں تو اس (احسان) کو مانیں (اور) شائد وہ (اسی سبب سے) پھر واپس آئیں.حلّ لُغَات.فِتْیَانٌ فِتْیَانٌ جمع فَتًی کی ہے اس کے معنے جوان کے ہیں لیکن جب کسی کی طرف مضاف ہو تو ا س کے معنے بیٹے یا نوکر کے ہوتے ہیں جیسے فَتَی زَیْدٍ زید کا بیٹا یا نوکر.اَلْبِضَاعَۃُ اَلْبِضَاعَۃُ طَائِفَۃٌ مِنَ الْمَالِ تُعَدُّ لِلتِّجَارَۃِ بِضَاعَۃٌ اس مال کو کہتے ہیں جو تجارت کے لئے تیار کیا جائے.(اقرب) الرِّحَالُ.اَلرَّحْلُ.اَیْضًا.مَرْکَبٌ لِلْبَعِیْرِ اَصْغَرُ مِنَ الْقَتَبِ.رِحَالٌ رَحْلٌ کی جمع ہے.اونٹ کے ہودج کو بھی کہتے ہیں.یہ قتب نامی ہودج سے چھوٹا ہوتا ہے.مَاتَسْتَصْحِبُہٗ مِنَ الْاَثَاثِ.اسی طرح جو سامان مسافر ساتھ لے اسے بھی رحل کہتے ہیں.وَقَدْ یُطْلَقُ عَلَی الْوِعَاءِ کَالْعِدْلِ وَالْجِرَابِ اور بورے تھیلے اور بیگ وغیرہ کی قسم کی چیزوں کو بھی جن میں سامان سفر بھرا جاتا ہے رحل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے.(اقرب) تفسیر.حضرت یوسفؑ کا اپنے بھائیوں سے احسان یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم ماتحت صبر کیا اور اس غیر معمولی رقت کو برداشت کیا جو قدرتاً بھائیوں کو دیکھ کر دل میں پیدا ہوئی تھی لیکن فطرتی محبت نے اس قدر احسان پر ضرور مجبور کر دیا کہ چلتے وقت جو قیمت انہوں نے دی تھی واپس کردی.اس کے یہ معنے نہیں کہ انہوں نے شاہی مال میں خیانت کی وہ خود وزیر تھے اور ایک قلیل رقم کا اپنی جیب سے ادا کردینا ان کے لئے مشکل نہ تھا.اصلاح محبت اور خوف کے بین بین سلوک سے ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سلوک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح محبت اور خوف کے بین بین سلوک سے ہوتی ہے پہلے ڈرایا تھا اب روپیہ واپس دے کر دل میں امید بھی پیدا کر دی تاکہ وہ ضرور واپس آئیں.
Page 478
لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَاۤ پہچا ن تو انہوں نے بہرحال لینا ہی تھا کیونکہ ان کا اپنا مال تھا مگر اس جگہ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حسنِ سلوک کی قدر کریں.کہتے ہیں فُلَانٌ لَایَعْرِفُ الْاِحْسَانَ.وہ احسان کی قدر نہیں کرتا پس حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ وہ احسان کی قدر کریں اور واپس آنے کی رغبت ان میں پیدا ہو.آنحضرت صلعم کی حضرت یوسفؑ سے سولہویں مشابہت حضرت یوسف کی طرح آنحضرت صلعم بھی اپنے بھائیوں سے ملنے کے لئے بے قرار تھے جیسا کہ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جذبۂ محبت کا ذکر کیا گیا ہے کہ باوجود بھائیوں کی مخالفت کے وہ اپنے بھائیوں کی ملاقات کے لئے بیقرار تھے یہی حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا.آپؐ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ(الشعراء:۴)کیا تو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنی جان کو ہلاک کر دے گا.غرض حضرت یوسفؑ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باوجود اہل مکہ کی سخت عداوت کے ان کی ہلاکت کی خواہش کی جگہ یہ زبردست خواہش تھی کہ وہ ایمان لاکر آپؐ سے مل جائیں.فَلَمَّا رَجَعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ پس جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہا (کہ) اے ہمارے باپ ہمیں (آئندہ کے لئے غلہ) ماپ (کر فَاَرْسِلْ مَعَنَاۤ اَخَانَا نَكْتَلْ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ۰۰۶۴ دینے) سے محروم کردیا گیا ہے اس لئے (اب) ہمارے بھائی (بن یامین) کو( بھی) ہمارے ساتھ بھیج کہ ہم (پھر غلّہ) ماپ (کرا کے) لے سکیں اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے.تفسیر.خدا تعالیٰ کی قدرت ہے.اب تک برادران یوسفؑ کو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے.حالانکہ اپنا ضعف ان پر ظاہر ہوچکا ہے.دین کے احساس کی کمزوری کا نتیجہ دین کا احساس کمزور ہوتو انسان کی یہی حالت ہوتی ہے.وہ سچے دل سے اپنے اندر کبر یا غرور محسوس کرتا ہے یا پھر مایوس ہو جاتا ہے.درمیانی راہ جو توکل کی ہے جس میں نہ کبر ہوتا ہے نہ مایوسی اس طرف نہیں آتا.برادرانِ یوسفؑ بھی ابھی اس مقام پر ہیں مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ میں مایوسی اور اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ میں اپنی طاقت کے گھمنڈ کا اظہار کرتے ہیں.مومن کو اس حالت سے بچنا چاہیے.
Page 479
قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَاۤ اَمِنْتُكُمْ عَلٰۤى اَخِيْهِ مِنْ اس نے کہا (تم ہی بتاؤ) کیا( اب یوسف کے تجربہ کے بعد بھی) میں اس کے متعلق تمہاری طرف سے مطمئن ہو سکتا قَبْلُ١ؕ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا١۪ وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ۰۰۶۵ ہوںسوائے اس کے کہ جس صورت میں پہلے میںاس کے بھائی کے متعلق تمہاری طرف سے مطمئن ہواتھا.اس لئے (میں اسے) اللہ( تعالیٰ کی حفاظت میں چھوڑ تا ہوں اور وہی سب سے )بہتر حافظ ہے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.حلّ لُغَا ت.ھَلْ اٰمَنُکُمْ اٰمَنُ اَمِنَ یَأْ مَنُ سے صیغہ واحد متکلم ہے اَمِنَہٗ کے معنے ہیں اس سے بے خوف ہو گیا.ھَلْ اٰمَنُکُمْ کیا میں تم سے بے خوف و مطمئن ہو جاؤں.عَلَیْہِ اس کے متعلق.عَلٰی اس جگہ متعلق کے معنے دیتا ہے.تفسیر.اللہ تعالیٰ ہی دل کو گند سے اور ظاہر کو برے عمل سے بچاتا ہے حضرت یعقوبؑ نے انہیں توجہ دلائی کہ اب تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر یقین کرو کہ دل کو گند سے اور ظاہر کو برے عمل سے وہی بچاتا ہے اور پہلے گناہوں کی بخشش بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہ انہیں یہ بھی توجہ دلاتے ہیں کہ نہ میں نے پہلے تم پر یقین کرکے یوسف کو تمہارے ساتھ بھجوایا تھا نہ اب اس کے بھائی کو تم پر اعتبار کرکے بھجواؤں گا.پہلے بھی میں نے اللہ کے حکم سے اور اس پر توکل کرکے یوسفؑ کو بھجوایا تھا اور اب بھی میرا اعتبار تم پر ویسا ہی ہوگا یعنی میں بھجوا تو دوں گا لیکن تم پر اعتبار کرکے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت اور اسی پر توکل کرکے بھجواؤں گا.وَ لَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی ان کی طرف واپس کر دی گئی ہے (اس پر) اِلَيْهِمْ١ؕ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا نَبْغِيْ١ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ انہوںنے (اپنے باپ سے) کہا( کہ) اے ہمارے باپ( اس سے بڑھ کر) ہم کیا چاہ سکتے ہیں (دیکھئے) یہ
Page 480
اِلَيْنَا١ۚ وَ نَمِيْرُ اَهْلَنَا وَ نَحْفَظُ اَخَانَا وَ نَزْدَادُ كَيْلَ ہماری پونجی ہے اسے (بھی) ہماری طرف واپس کر دیا گیا ہے اور(اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو) ہم اپنے بَعِيْرٍ١ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ۰۰۶۶ گھر والوں کو خوراک کا سامان لا دیںگے اور اپنے بھائی کی( ہر طرح سے) حفاظت کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لیں گے وہ (غلہ کا) وزن (جو ہم پہلے لائے ہیں) تھوڑا ہے.حلّ لُغَات.مَتَاعٌ.مَتَاعٌ عام ضروریات کی چیزوں کو کہتے ہیں.جیسے خوراک پوشاک.گھر کے استعمال کا سامان آلات اور اجناس (اقرب) (مزید تشریح کے لئے دیکھیں یونس آیت۲۴ و ہودآیت ۴) بِضَاعَۃٌ پونجی (دیکھو یوسف آیت۶۳) نَمِیْرُ نَمِیْرُ مَارَفُلَانٌ عَیَالَہٗ.اَتَاھُمْ بِمِیْرَۃٍ مَارَ کے معنے ہیں اپنے اہل کو غلہ لا دیا.پس نَمِیْرُ کے معنے ہوئے اپنے اہل کو غلہ لاکر دیں گے.(اقرب) تفسیر.بائبل اور قرآن مجیدکے بیان میں اختلاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے علاوہ خریدے ہوئے غلہ کے اپنے بھائیوں کو راستہ کے خرچ کے لئے کچھ زائد غلہ دے دیا تھا.گو واضح الفاظ میں یہ بات بیان نہیں ہوئی لیکن اونٹ کے بوجھ برابر غلہ لانے کے الفاظ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اونٹوں پر سفر کیا تھا.بائبل کا بیان کہ برادران یوسفؑ نے گدھوں پر سفر کیا لیکن بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے گدھوں پر سفر کیا تھا.چنانچہ لکھا ہے ’’اور اس شخص نے ان مردوں کو یوسفؑ کے گھر میں لاکر پانی دیا کہ پاؤں دھوئیں اور ان کے گدھوں کو دانہ گھاس دیا.‘‘ (پیدائش باب ۴۳ آیت ۲۴).قرآن مجید کا بیان کہ برادران یوسفؑ نے اونٹوں پر سفر کیا قرآن مجید میں اور موقع پر بھی جہاں صواع کی تلاش کا ذکر ہے اونٹ کا ہی ذکر آیا ہے.چنانچہ فرماتا ہے وَ لِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ کہصُوَاعَ الْمَلِكِ لانے والے کو ایک اونٹ کے بوجھ برابر غلہ دیا جائے گا.یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے اور قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم ان اختلافات پر بھی جہاں تک ہوسکے روشنی ڈالیں کیونکہ گو ایمانی طور پر تو ہم قرآنی بیان کو مقدم
Page 481
مانتے ہیں لیکن اہل کتاب کو سمجھانے کے لے ہمارے پاس زائد دلیلیں ہونی چاہئیں.اختلاف کا فیصلہ میرے نزدیک اس اختلاف کا فیصلہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب اور ان کا گھرانہ کس سواری پر عام طور پر سواری کیا کرتا تھا.جو سواری دوسرے حوالہ جات سے ثابت ہو تاریخی طور پر اس سفر میں بھی اسی کو ترجیح دی جائے گی.بائبل میں حضرت یعقوبؑ کے ایک اور سفر کا ذکر ہے یعنی جبکہ وہ اپنی بیویوں کو اپنے سسرال کے ہاں سے لے کر واپس آئے ہیں.اس سفر کے متعلق بائبل میں لکھا ہے: ’’تب یعقوبؑ نے اٹھ کے اپنے بیٹوں اور اپنی جورؤں کو اونٹوں پر بٹھایا.‘‘ (پیدائش باب ۳۱ آیت ۱۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے گھرانے کو اونٹ پر سفر کرنے کی عادت تھی.پس بائبل کے اس ثبوت کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس راستہ کی نوعیت کو مدنظر رکھتے ہوئے جس میں اونٹ کا سفر گدھے کے سفر سے زیادہ آرام دہ رہتا ہے ہمیں عقلاً بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یوسفؑ کے بھائیوں نے اونٹوں پر ہی سفر کیا ہوگا.بائبل اور قرآن مجید کے بیانات میں تطبیق لیکن یہ تشریح اس امر کو فرض کرکے ہے کہ قرآن کریم سے اونٹوں پر سفر ثابت ہے.جو لوگ اس استدلال کو قوی نہ سمجھتے ہوں وہ یوں اس مشکل کو حل کرسکتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اونٹوں پر سوار تھے حِمْلُ بَعِیْرٍ سے اونٹ کے اٹھانے کے قابل وزن مراد ہے.آگے خواہ وہ اس کو گدھوں پر لادیں اس صورت میں دونوں حوالوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا.قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے اللہ (تعالیٰ)کی طرف سے (مقرر شدہ یعنی اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ١ۚ فَلَمَّاۤ اٰتَوْهُ اس کی قسم سے موکدیہ) عہد نہ کرو.کہ تم اسے ضرور میرے پاس (واپس) لاؤ گےسوائے اس( صورت) کے کہ تم
Page 482
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ۰۰۶۷ (خود کسی مصیبت میں) گھر جاؤپس جب انہوں نے اسے اپناپختہ قول دےدیا تو اس نے کہاجو (کچھ) ہم( اس وقت) کہہ رہے ہیں اللہ اس کا نگران ہے.حلّ لُغَات.یُحَاطَ بِکُمْ اَنْ یُحَاطَ بِکُمْ.اُحِیْطَ بِہٖ دَنَا ھَلَاکُہٗ وَفِی الْقُرْاٰنِ اِلَّا اَنْ یُحَاطَ بِکُمْ: اُحِیْطَ بِہٖ کے معنے ہیں ہلاکت کے منہ میں آ گیا.ہرطرف سے تباہی کے منہ میں گھر گیا.چنانچہ قرآن کریم میں اِلَّاۤ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے.(اقرب) اَلْمَوْثِقُ وَالْمِیْثَاقُ الْعَہْدُ عہد اقرار.(اقرب) وَکِیْلٌ.نگران.(مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت ۱۰۵) تفسیر.آنحضرتؐ کی بن یامین سے ایک مشابہت اس جگہ پر بن یامین کے ساتھ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشابہت ہو گئی ہے.جب مدینہ والے لوگ آپؐ کو لینے کے لئے آئے تو آپؐ کی طرف سے حضرت عباسؓ نے ان سے معاہدہ کیا کہ تم لوگ اپنی جان اور مال سے آپؐ کی حفاظت کرو گے.انہوں نے یہ اقرار کیا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام، امر العقبۃ الثانیۃ).بائبل میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوبؑ نے عہد کا مطالبہ کیا تو روبن نے جو سب لڑکوں سے عمر میں بڑا تھا کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں تو ان کو اپنے پاس رکھ لے.اگر میں بن یامین کو نہ لے آؤں تو ان کو قتل کر دیجیئو.مگر حضرت یعقوبؑ نے اس کی بات کو رد کر دیا.اور اس کے کہنے پر بن یامین کو نہ بھیجا.(پیدائش باب ۴۲ آیت ۳۷) برادران یوسف ؑمیں سے یہودا دینی لحاظ سے بڑا سمجھا جاتا تھا لیکن جب یہودا نے اپنے باپ کے نزدیک آکر قسم کھائی اور سب کی طرف سے معاہدہ کیا تو حضرت یعقوبؑ نے اس کی بات مان لی.(پیدائش باب ۴۳ آیت ۸تا۱۳) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی لحاظ سے وہی سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا.یہ حوالہ اسی سورۃ کی ایک اگلی آیت کا مضمون سمجھنے میں کارآمد ہوگا.
Page 483
وَ قَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّ ادْخُلُوْا مِنْ اور اس نے (ان سے) کہا (کہ) اے میرے بیٹو (وہاں) تم (سب) ایک ہی دروازے سے اندر نہ جانا اور اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ١ؕ وَ مَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ١ؕ ( جب حاکم کے پاس جانا پڑے) الگ الگ دروازوں سے اندر جانا اور میں اللہ (تعالیٰ کی گرفت) سے( بچانے اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ١ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ١ۚ وَ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ کے لئے) کچھ بھی تمہارے کام نہیں آسکتا.فیصلہ کرنا( دراصل) اللہ( تعالیٰ) ہی کا کام ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا الْمُتَوَكِّلُوْنَ۰۰۶۸ ہے اور تمام بھروسہ کرنے والوں کواسی پر بھروسہ کرنا چاہیے.حلّ لُغَات.اَلْحُکْمُ اَلْحُکْمُ: حَکَمَ بِالْاَمْرِ حُکْمًا وَحُکُوْمَۃً.حُکْمٌ.حَکَمَ یَحْکُمُ کا مصدر ہے اور حَکَمَ کے معنے ہیں قَضٰی اس نے فیصلہ کیا.وَالْحُکْمُ اَلْقَضَاءُ اور حُکْمٌکے معنی ہیں فیصلہ کرنا.(اقرب) حَکَمَ.اَصْلُہٗ مَنَعَ مَنْعًا لِاِصْلَاحٍ.حَکَمَ کے اصل معنی اصلاح کی خاطر کسی کام سے روکنے کے ہیں اور اسی وجہ سے جانور کی لگام کو حَکَمَۃٌ کہتے ہیں وَالْحُکْمُ بِالشَّیْءِ اَنْ تَقْضِیَ بِاَنَّہٗ کَذَا اَوْ لَیْسَ بِکَذَا سَوَاءٌ اَلْزَمْتَ ذٰلِکَ غَیْرَکَ اَوْلَمْ تُلْزِمْہُ اور حکم کے یہ معنی ہیں کہ کسی امر کے متعلق یہ فیصلہ کیا جائے کہ وہ اس اس طرح ہے یا اس اس طرح نہیں.خواہ وہ بات دوسرے پر واجب کی جائے یا نہ.(مفردات) تَوَکَّلَ عَلَی اللہِ تَوَکَّلَ عَلَی اللہِ.اِسْتَسْلَمَ اِلَیہِ وَاعْتَمَدَ وَوَثِقَ بِہٖ توکل علی اللہ کے معنی ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کردیا اور اسی پر بھروسہ و اعتماد کیا.(اقرب) تفسیر.حضرت یعقوبؑ کی اپنے بیٹوں کو علیحدہ علیحدہ داخل ہونے کی نصیحت چونکہ انہوں نے مصر کے حالات نہایت ڈر ڈر کر بیان کئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہمیں وہاں جاسوس سمجھا گیا تھا اس لئے حضرت یعقوبؑ نے یہ نصیحت کی کہ علیحدہ علیحدہ داخل ہونا اکٹھے ایک جتھے کی صورت میں داخل نہ ہونا.تاکہ لوگوں کو غیر ملکی سمجھ کر شبہ کا موقع نہ ملے مگرا نہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت مقدر ہے تو میں
Page 484
کچھ نہیں کرسکتا.حضرت یعقوبؑ کو الہاماً حالات معلوم ہوگئے تھے یہ معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ یوسفؑ کے پاس جاتے ہوئے الگ الگ دروازوں سے جانا.اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ انہیں الہاماً حالات معلوم ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بن یامین کو یوسف ؑ سے الگ ملنے کا موقعہ مل جائے تاکہ وہ انہیں گھر کے حالات سے مطلع کر دیں.عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ کا مطلب عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میرا اصل یقین خدا کی ذات پر ہے نہ اپنی تدبیر پر.اور اپنے لڑکوں کو جو ہمیشہ اپنی تدابیر پر بھروسہ کرتے تھے سبق دیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے نبی جو عقلاً بھی دنیا سے ممتاز ہوتے ہیں الٰہی نصرت کو ہی اصل چیز تصور کرتے ہیں تو دوسرے کیوں ایسا نہ کریں؟ توکل کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ انسان تدبیر نہ کرے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ باوجود تدبیر کے خدا تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرے اور یقین رکھے کہ تدبیر بھی تبھی نفع دیتی ہے جب خدا تعالیٰ کی نصرت ساتھ ہو.وَ لَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ١ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ اور جب اس طریق کے مطابق جس کا حکم ان کے باپ نے انہیں دیا تھا.وہ داخل ہوئے تو (وہ غرض پوری ہوگئی جس عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ کے لئے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا لیکن) وہ اللہ( کی گرفت) سے (بچانے کے لئے) ان کے کچھ بھی کام نہیں آسکتا تھا يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا١ؕ وَ اِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَ لٰكِنَّ ہاں مگر یعقوبؑ کے دل میں ایک خواہش تھی جسے اس نے (اس طرح) پورا کرلیا.اور اس وجہ سے کہ اسے ہم نے علم اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَؒ۰۰۶۹ بخشا تھا.وہ بڑے علم والا تھا لیکن اکثر لوگ( اس حقیقت کو )نہیں جانتے.حل لغات.اَلْحَاجَۃُ.اَلْحَاجَۃُ اَلسُّؤْلُ.حاجت کے معنی ہیں مطلوب، خواہش.(اقرب) تفسیر.حضرت یعقوبؑ کو یوسف ؑکے زندہ ہونے کا علم تھا.گو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ یوسفؑ زندہ ہیں لیکن انہیں قطعی طور پر اس کا علم نہ تھا کہ مصر کے غلہ بانٹنے والے وزیر وہی ہیں.
Page 485
پس اپنے بیٹوں کے اس خوف سے متاثر ہوکر کہ مصری ہمیں جاسوس سمجھتے تھے بیٹوں کو یہ تجویز بتائی تھی.چونکہ حضرت یوسفؑ نے پہلی دفعہ ان پر بہت سے ایسے سوال کئے تھے جن سے انہیں شبہ پیدا ہو ا کہ شاید یوسف ہمیں جاسوس سمجھتے ہیں اور وہی باتیں انہوں نے حضرت یعقوبؑ کو بتائیں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے ان کے شبہ کی وجہ سے احتیاطاً ہدایت کی کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا.وَ اِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍمیں علم سے مراد توکل ہے وَ اِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ.میں علم سے مراد توکل ہے.جس کا پہلے ذکر ہوچکا ہے اور یہی وہ معرفت اور علم تھا جو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا یعنی انہوں نے تدبیر بھی کرلی مگر توکل پھر بھی خدا پر ہی رکھا.علیحدہ علیحدہ داخل ہونے کی نصیحت نظر لگ جانے کے خوف سے نہ تھی بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت یعقوبؑ کو نظر لگ جانے کا خوف تھا.اس تدبیر سے انہوں نے اس کو دور کر لیا (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھٰذا) لیکن یہ معقول نہیں.ایک بھائی کے بڑھ جانے سے نظر لگ جانے کا خطرہ کس طرح پیدا ہو گیا تھا؟ پہلے بھی تو دس بھائی اکٹھے گئے تھے.اس وقت کیوں یہ تدبیر نہ کی! پس اصل بات یہی ہے کہ جب مصر سے واپسی پر برادرانِ یوسفؑ نے جاسوسی کے احتمال کو پیش کیا تو حضرت یعقوب نے ان کو مزید احتیاط برتنے کا مشورہ دیا.حضرت یعقوب نے علیحدہ علیحدہ داخل ہونے کی نصیحت اس لئے کی تا بن یامین حضرت یوسف کو مل سکیں یا جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے انہیں چونکہ الہام سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ حاکم جو غلہ دیتا ہے یوسفؑ ہے انہوںنے الگ الگ ملنے کا حکم دیا تاکہ بن یامین یوسفؑ سے علیحدگی میں مل سکیں.وَ لَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْۤ اَنَا اور جب وہ یوسف کے حضور حاضر ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی.اور( اس سے) کہا (کہ) یقیناً اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَىِٕسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰۰۷۰ میں ہی تیرا (مفقود) بھائی ہوں.پس جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے (اب) تو غمگین نہ ہو.حلّ لُغَات.اٰوٰٓی اِلَیْہِ.اٰوَیْتُہٗ.اَنْزَلْتُہٗ اٰوَیْتُہٗ کے معنے ہیں میں نے اسے اپنے پاس اتارا.اپنے
Page 486
ہاں ٹھہرایا وَمِنْہُ اللّٰہُمَّ اٰوِنِیْ اِلٰی ظِلِّ کَرَمِکَ وَعَفْوِکَ.انہی معنوں میں اس دعا میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اے اللہ! مجھے اپنے کرم اور عفو کے سایہ میں جگہ دے.(اقرب) (نیز دیکھو ہودآیت ۴۴) لَاتَبْتَئِسْ.اِبْتَأَسَ بِہٖ.اِکْتَئَبَ وَاسْتَکَانَ.غمگین اور دل شکستہ ہوا.اور لَاتَبْتَئِسْ کے معنے ہیں لَاتَحْزَنْ وَلَا تَشْتَکِ.نہ غم کر اور نہ شکایت (اقرب) (مزید تشریح کے لئے دیکھو ہودآیت ۳۷).تفسیر.لَا تَبْتَئِسْ کے دو معنے اگر تو یہ سمجھا جائے کہ بھائی کو کوئی علم حقیقت کا نہ تھا تو لَاتَبْتَئِسْ کا ایک تو یہ مطلب لیا جائے گا کہ تجھے جو خیال تھا کہ میں مر گیا ہوا ہوں اور اس کا تجھے غم تھا اب تو اس غم کو دور کر دے کیونکہ میں زندہ موجود ہوں لیکن اگر یہ معنے کئے جائیں کہ بن یامین کو حضرت یعقوبؑ نے اطلاع دے دی تھی تو پھر اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ جو تکالیف وہ تجھ کو دیتے رہے ہیں اب خدا تعالیٰ اس سے تجھے نجات دینے والا ہے.فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ پھر جب اس نے انہیں ان کا سامان دے کر( واپسی کے لئے) تیار کیا تو اس نے (پانی پینے کا ایک) کٹورا( بھی) اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ۰۰۷۱ اپنے بھائی کے بورے میں رکھ دیا پھر( ایسا ہوا کہ) کسی اعلان کرنے والے (شاہی کارندہ) نے اعلان کیا( کہ) اے قافلہ والو تم یقیناً چور ہو.حلّ لُغَات.جَھَّزَھُمْ جَھَّزَھُمْ بِجَھَازِھِمْ.اس نے انہیں ان کا سامان دے کر تیار کیا.(مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف آیت۶۰) اَلسِّقَایَۃُ.اَلْاِنَاءُ یُسْقٰی بِہٖ.سِقَایَۃٌ کے معنی ہیں پانی پینے کا برتن جیسے کٹورا، پیالہ وغیرہ.(اقرب) اَلْعِیْرُ.قَافِلَۃُ الْحَمِیْرِ ثُمَّ کَثُرَتْ حَتّٰی سُمِّیَتْ بِھَا کُلُّ قَافِلَۃٍ.عِیْر کے اصل معنے تو گدھوں پر مال لاد کر سفر کرنے والے قافلہ کے ہیں لیکن کثرت استعمال کے ماتحت ہر ایک قافلہ کو عیر کہا جاتا ہے.(اقرب) اَلْعِیْرُ.اَلْقَوْمُ الَّذِیْنَ مَعَھُمْ اَحْمَالُ الْمِیْرَۃِ.غلہ لے جانے والا قافلہ.(مفردات) اَلرَّحْلُ: بورا (مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف آیت۶۳) تفسیر.جَعَلَ السِّقَایَۃَ کے دو معنے جَعَلَ السِّقَایَۃَ کے دو معنے ہوسکتے ہیں.
Page 487
۱.جان بوجھ کر پیالہ رکھ دیا اور یہ محبت کے جذبہ کی وجہ سے تھا کہ تا راستہ میں پیاس کے وقت اس میں پانی پئے.۲.بھول کر رکھ دیا اور یہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ اپنے بھائی سے باتیں کرتے ہوئے پانی منگایا اور پینے کے بعد وہیں بھول کر پیالہ رکھ دیا.قَالُوْا وَ اَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّا ذَا تَفْقِدُوْنَ۰۰۷۲قَالُوْا نَفْقِدُ انہوں نے ا ن (شاہی کارندوں) کی طرف رخ کر کے کہا (کہ) تم کیا چیز گم پاتے ہو.انہوں نے کہا (کہ) ہم غلہ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّ اَنَا بِهٖ ماپنے کا شاہی پیمانہ گم پاتے ہیں.اور جو شخص اسے (تلاش کر کے) لے آئے تو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر( غلہ) زَعِيْمٌ۰۰۷۳ اس کا (انعام) ہو گا اور(اعلان کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ) میں اس کا ذمہ وار ہوں.حلّ لُغَات.اَقْبَلَ عَلَیْہِ.نَقِیْضُ اَدْبَرَ.اَقْبَلَ عَلَیْہِ کے معنی ہیں اس کی طرف رخ کیا.(اقرب) اَلْاِقْبَالُ.اَلتَّوَجُّہُ نَحْوُالْقُبُلِ.سامنے آنا رخ کرنا.(مفردات) قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَیْہِمْ کے معنے ہوئے کہ انہوں نے ان کی طرف رخ کرکے کہا.صُوَاعٌ.صُوَاعٌ اَلْمِکْیَالُ الَّذِیْ یُکَالُ بِہٖ.صُوَاع غلہ ماپنے کا ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے.اَلْجَامُ الَّذِیْ یُشْرَبُ فِیْہِ.پانی پینے کے جام کو بھی صُوَاع کہتے ہیں.(اقرب) اَلزَّعِیْمُ اَلْکَفِیْلُ زعیم کے معنے ضامن اور ذمہ وار کے ہیں.(اقرب) تفسیر.اس جگہ اختلاف ہوا ہے.بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ برتن جان بوجھ کر بھائی کے اسباب میں رکھ دیا.اس کے بعد کہا کہ تم چور ہو.یہ یوسف علیہ السلام پر افترا ہے.ایک طرف تو بھائی کے ساتھ اتنی محبت دوسری طرف چند دن کی صحبت کی غرض سے اس کے اسباب میں برتن رکھ کر اس پر چوری کا الزام لگانا اور ساری عمر کے لئے اسے داغ دار کر دینا نہ صرف یوسف علیہ السلام کو جھوٹ کا بلکہ ظلم کا مرتکب بناتا ہے
Page 488
اور یہ کام نبی تو کیا ایک معمولی شریف آدمی بھی نہیں کرسکتا.دراصل یہ قصور بائبل کا ہے جس نے یہ قصہ پیش کیا اور ہمارے مفسروں نے سادہ لوحی سے اسے نقل کر دیا.مَلَک کے لفظ کا استعمال حضرت یوسف ؑکے لئے خوشامدانہ ہے مَلَک کا لفظ یا تو حضرت یوسفؑ کے لئے خوشامدانہ رنگ میں استعمال کیا ہے جیسے غرباء بڑے لوگوں کو بادشاہ کہہ کر پکارتے ہیں یا پھر سرکاری کام کے وقت سرکاری برتن استعمال کئے جاتے ہوں گے اور انہیں بادشاہ کا برتن کہنا بالکل درست ہے.گمشدہ پیالہ قیمتی تھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیالہ قیمتی تھا تبھی اس کے ڈھونڈنے والے کے لئے ایک اونٹ کا بوجھ انعام رکھا ہے.اتنا انعام چاندی سونے کے برتن کے لئے ہی رکھا جاسکتا ہے.یہ اعتراض نہیں ہوسکتا کہ چاندی سونے کے برتن استعمال کرنے تو منع ہیں کیونکہ یہ اسلامی حکم ہے.یہود میں ایسی ممانعت نہیں نہ فراعنۂ مصر اس کو برا سمجھتے تھے.حضرت یوسف ؑ پر یہود کے الزام کی تردید یہ سوال کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی کے اسباب میں کیا چیز اور کس ارادہ سے رکھی اور پھر چوری کا الزام ان پر کس طرح لگا؟ لوگوں کے لئے ہمیشہ زیربحث رہا ہے.جیسا کہ میں نے اوپر بتایا ہے یہود کا یہ خیال ہے کہ حضرت یوسفؑ نے جان کر ایک برتن رکھ دیا.پھر چوری کا الزام لگا کر ان کو اپنے پاس رکھ لیا.لیکن یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی کی طرف اس کا منسوب کرنا کفر ہے.بن یامین کو حضرت یوسفؑ پاس رکھنے کی الٰہی تدبیر میرے نزدیک اس مشکل کا حل خود قرآن کریم سے ہی ہو جاتا ہے.قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پانی پینے کا برتن خود اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کے اسباب میں رکھا تھا پھراس میں یہ بھی ہے کہ ایک صُوَاعٌ یعنی ماپنے کا برتن بھی گم ہو گیا جو تلاش پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے اسباب میں سے نکلا.حضرت یوسفؑ نے پانی پینے کا برتن اپنی محبت کے اظہار کے لئے بھائی کے سامان میں رکھا تھا برتن کا بھائی کے اسباب میں رکھنا کوئی ایسا واقعہ نہ تھا کہ جسے قرآن کریم ذکر کرتا.جب تک اس میں کوئی غرض نہ ہوتی اور وہ غرض یہی معلوم ہوتی ہے کہ پینے کا برتن بغیر بھائی کو علم دینے کے حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا تا اس طرح اپنی محبت کا اظہار کریں.اس برتن کے رکھتے ہوئے ماپنے کا سرکاری برتن جو غالباً اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا بھول کر ساتھ ہی رکھا گیا.جب وہ برتن نہ ملا تو نوکروں نے اسے چوری قرار دے کر تلاشی لینی شروع کی.سب قافلے کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی تلاشی لینی ضروری تھی.مگر حضرت یوسف کی مہربانی کو دیکھ کر
Page 489
اعلان کرنے والے نے بن یامین کی تلاشی بعد میں لی اور علاوہ اس پیالہ کے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود رکھا تھا ماپنے کا برتن بھی اسباب میں سے نکل آیا.حضرت یوسف علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ کیا غلطی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس واقعہ میں الٰہی تدبیر دیکھ کر اس وقت تک خاموشی رکھی جب تک بھائیوں کا قافلہ چلا نہیں گیا اور اس طرح ان کا بھائی ان کے پاس ہی رہ گیا.قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ انہوں نے کہا( کہ) اللہ( تعالیٰ) کی قسم (جیسا کہ) تمہیں یقیناً علم ہو چکا ہے ہم (یہاں) اس لئے نہیں آئے کہ اس وَ مَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ۰۰۷۴قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗ اِنْ كُنْتُمْ ملک میں فسادکریں اور نہ( ہی) ہم چور ہیں.انہوں نے کہا (کہ) اگر تم جھوٹے (ثابت) ہوئے تو اس( فعل یعنی كٰذِبِيْنَ۰۰۷۵قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ چوری) کی سز ا کیا ہوگی.انہوں نے کہا( کہ) اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں وہ (کٹورا) پایا جاوے جَزَآؤُهٗ١ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ۰۰۷۶ وہ( خود ہی) اس (فعل) کا بدلہ ہو ہم( لوگ) ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں.تفسیر.یہ خدا تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ بھائیوں نے جوش میں آکر کہہ دیا کہ جس کے اسباب میں سے پیالہ نکلے اسی کو اپنے پاس رکھ لینا.ان کے منہ سے یہ نہ نکلا کہ جس نے چوری کی ہو اگر وہ یہ کہتے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو شاید نہ رکھ سکتے کیونکہ اس سے اس پر حتمی طور پر چوری کا الزام لگتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے لفظ ہی یہ کہے کہ جس کے اسباب میں سے پیالہ نکلے اسے رکھ لینا.حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر چوری کا الزام لگانے کے بھائی کو پاس رکھنے کا موقع مل گیا.
Page 490
فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ۠ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ پس اس نے اس کے( یعنی یوسف کے) بھائی کے بورے سے پہلے ان (دوسروں) کے بوروں کو( دیکھنا) شروع وِّعَآءِ اَخِيْهِ١ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ١ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ کیا.پھر اس کے بھائی کے بورے (کو دیکھا اور اس میں اس پیالہ کو پا کر اس) میں سے اسے نکالا.اس طرح ہم اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ١ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ نے یوسف کے لئے(ایک) تدبیر کی( ورنہ) وہ بادشاہ کے قانون کے اندر( رہتے ہوئے) اپنے بھائی کو روک( کر مَّنْ نَّشَآءُ١ؕ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ۰۰۷۷ اپنے پاس )نہیں (رکھ) سکتا تھا.سوائےاس (صورت) کے کہ اللہ( تعالیٰ) کی (یہی) مشیت ہوتی.ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر (اس سے )زیادہ علم والا( شخص پایا جاتا)ہے.حلّ لُغَات.بَدَأَ بَدَأْتُ بِالشَّیْءِ کے معنے ہیں اِبْتَدَأْتُہٗ اسے شروع کیا.بَدَأَ بِفُلَانٍ قَدَّمَہٗ اسے پہلے رکھا اور بَدَأَ بِاَوْعِیَتِھِمْ کے معنے ہوں گے پہلے ان دوسروں کے بوروں کو دیکھنا شروع کیا.(اقرب) (مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت۶) اَلْوِعَاءُ.اَلظَّرْفُ یُوْعٰی فِیْہِ الشَّیءُ.وِعَاءٌ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں سامان کو محفوظ کرکے رکھا جائے اس کی جمع اَوْعِیَۃٌ ہے.(اقرب) کَادَلَہٗ اِحْتَالَ لَہٗ جب کَادَ کا صلہ لام آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے حق میں تدبیر کی اور کِدْنَا لِیُوْسُفَ کے معنے ہوئے ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی.(اقرب) یَاْخُذُ.یَاْخُذُ اَخَذَ میں سے ہے جس کے معنے ہیں حَبَسَہٗ.اسے روک لیا.(اقرب) الدِّیْنُ دَانَ دِیْنًا.اَطَاعَ.دَانَ جس کا مصدر دین ہے اس کے معنے ہیں اطاعت کی فُلَانًا خَدَمَہٗ خدمت کی.خدمت ادا کی.حَکَمَ عَلَیْہِ.حکم لگایا، فیصلہ کیا.اَلدِّیْنُ اَلطَّاعَۃُ دین کے معنی ہیں فرمانبرداری.اَلْقَضَاءُ.فیصلہ.(اقرب)
Page 491
وَاسْتُعِیْرَ لِلشَّرِیْعَۃِ اور یہ لفظ بالواسطہ شریعت یا قانون کے معنے میں بھی استعمال ہوتا ہے.(مفردات) تفسیر.بَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ۠ میں تلاشی لینے والا اعلان کرنے والا ہی تھا بَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ۠ میں تلاشی لینے والا وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس نے اعلان کیا تھا نہ کہ حضرت یوسفؑ اور قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ سے مراد حضرت یوسفؑ کے بھائی سے ہے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پاس ہی گزرا ہے اس طرح ضمیر کو پھیرا جاسکتا تھا.بِن یامین کی تلاشی سب سے آخر میں ان کے ادب کی وجہ سے لی اس تلاشی لینے والے نے بن یامین کی تلاشی سب سے آخر اس لئے نہیں لی کہ وہ جانتا تھا کہ آخر میں ان کے اسباب سے پیالہ نکالوں گا بلکہ اس لئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ان پر مہربانی دیکھ کر وہ طبعاً ان کا ادب کرنا چاہتا تھا اور ان پر گمان بھی نہیں کرسکتا تھا کہ ان کے اسباب میں سے پیالہ نکلے گا.كِدْنَا لِيُوْسُفَ سے معلوم ہوتا ہے کہ بن یامین کو حضرت یوسف کے پاس رکھنے کی تدبیر خدا کی طرف سے تھی كِدْنَا لِيُوْسُفَ سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تدبیر کی تھی.پھر تعجب ہے کہ مفسرین یوسف علیہ السلام پر ہی الزام دھرتے چلے جاتے ہیں.حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سامان پیدا کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے بھول کر برتن رکھ دیا.بھائیوں کے منہ سے نکل گیا کہ جس کے اسباب میں برتن نکلے اسے پکڑ لینا اور اس طرح وہ بھائی کو پیچھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے.ان کے جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اصل حقیقت ظاہر کر دی ہوگی اور بن یامین کی برأت لوگوں کی نظر میں ہو گئی ہوگی.پس یہ سب ایک الٰہی تصرف کے ماتحت ہوا.بھائیوں کو شور کرنے کا موقع بھی نہ ملا اور بن یامین یوسف علیہ السلام کے پاس رہ بھی گئے.مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ میں فی کے معنے سبب کے ہیں مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ.فِیْ کے معنی سبب کے بھی ہوتے ہیں.جیسے حدیث میں آتا ہے عُذِّبَتْ إِمْرَاۃٌ فِی ھِرَّۃٍ حَبَسَتْھَا حَتّٰی مَاتَتْ جُوْعًا فَدَخَلَتْ فِیْھَا النَّارَ(بخاری کتاب المساقاۃ باب فضل سقی المآء).یعنی ایک عورت عذاب میں مبتلا کی گئی صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور وہ بیچاری بھوکی مر گئی.فِیْ کے ان معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ قانونِ شاہی کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے.پس اللہ تعالیٰ نے ان کے روکنے کی ایک تدبیر پیدا کردی.کسی کے قانون کے ماتحت رہنا نبی کی شان کے خلاف نہیں اس آیت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب
Page 492
کسی بادشاہ کی حکومت میں رہے تو اس کے قانون کی فرمانبرداری کرے.حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے لیکن فرعون کے قانون کی پابندی کرتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی شان کے خلاف تھا کہ بادشاہ کے قانون کے خلاف اپنے بھائی کو زبردستی رکھ لیتے.پس معلوم ہوا کہ کسی کے قانون کے ماتحت رہنا نبی کی شان کے خلاف نہیں بلکہ کسی کی حکومت میں رہ کر قانون شکنی کرنا شان کے خلاف ہے مگر افسوس کہ مسلمان عام طور پر اس مرض میں مبتلا ہیں کہ غیرمذہب کے بادشاہ کی اطاعت کو جائز نہیں سمجھتے.اس غداری کی روح نے ان کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور ان کی دیانت کی روح کچلی گئی ہے.مسلمان کو بے شک ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن دھوکے سے نہیں، صفائی اور سچائی سے.جب کسی کے ملک میں کوئی رہتا ہے تو عملاً اقرار کرتا ہے کہ فرمانبرداری سے گزارہ کرے گا.ظاہر میں یہ اثر ڈال کر دل میں غداری کا خیال رکھنا بہت بے انصافی ہے اور خود اپنے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے کیونکہ ایسا آدمی اپنے نفس میں سمجھتا ہے کہ میں منافقت کررہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی موجودہ بزدلی بہت کچھ اس گندے عقیدہ کی وجہ سے ہے.فرمانبرداری انسان کو حکومت سے محروم نہیں کر دیتی ہم جس کا چاہتے ہیں درجہ بڑھاتے ہیں.اس میں یہ بتایا ہے کہ ایسی فرمانبرداری انسان کو حکومت سے محروم نہیں کردیتی.اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی ترقی کے لئے خود ہی سامان پیدا کردیتا ہے کیونکہ وہ تمام علموں کا سرچشمہ اور سب سامانوں کا مالک ہے.قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ١ۚ فَاَسَرَّهَا انہوں نے (یعنی اس کے بھائیوں نے) کہا (کہ) اگر اس نے چوری کی ہو تو( کچھ عجب نہیں کیونکہ) اس کا ایک يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَ لَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ١ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ بھائی (بھی) پہلےچوری کر چکا ہے اس پر یوسفؑ نے اس (بات کی اصل حقیقت) کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور مَّكَانًا١ۚ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ۰۰۷۸ ان پر اسے ظاہر نہ کیا(ہاں اتنا) کہا (کہ) تم( لوگ) بدترین حیثیت کے (معلوم ہوتے )ہو اور جو بات تم کہتے ہو اسے اللہ( تعالیٰ ہی) بہتر جانتا ہے.حلّ لغات.مَکَانًا.مَکَانًا کَانَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ بِمَکَانٍ.اَیْ رُتْبَۃٍ وَمَنْزَلَۃٍ.کَانَ مِنَ
Page 493
الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ بِمَکَانٍ کے معنے ہیں کہ عقل اور علم میں بڑے پایہ اور حیثیت کا تھا.پس مکان کے معنے حیثیت کے ہوئے.(اقرب) تفسیر.ایک جرم سے دوسرے جرم کی جرأت پیدا ہوتی ہے جرم کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جرم کی جرأت پیدا ہوجاتی ہے.یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہلے یوسفؑ کو جان سے مارنا چاہا تھا اب ان کی اخلاقی موت کے طالب ہوتے ہیں اور کس ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ بن یامین نے چوری کی تو کیا ہوا اس کا بھائی یعنی یوسفؑ بھی اس سے پہلے چوری کرچکا ہے ان کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک سچی توبہ ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی.مفسرین کا حضرت یو سفؑ پر چوری کا الزام مفسرین پر تعجب ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ بھائیوں نے جھوٹ بولا یوسف کی چوری کی تلاش میں لگ گئے ہیں اور بعض نے تو یہاں تک کمال کیا ہے کہ لکھ دیا ہے کہ جب وہ بچے تھے تواپنی پھوپھی کے ہاں کی بعض چیزیں اٹھا لائے تھے(درمنثور زیر آیت ھٰذا) سُبْحَانَکَ اِنْ ھٰذَا اِلَّابُھْتَانٌ عَظِیْمٌ.حضرت یوسف ؑکے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ یوسف علیہ السلام کے دل کی جو کیفیت ان کی اس بات کو سن کر ہوئی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے مگر باوجود طاقت کے خاموش ہو گئے اور غصہ پی گئے.دل میں افسوس کر چھوڑا.یہ کیسا اعلیٰ درجہ کا مقام ہے.بہت لوگ بے طاقت ہوکر غصہ کا شکار ہوجاتے ہیں.حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کی طاقت تھی مگر خاموش ہو رہے اور بھائیوں کے ناپاک الزام کو برداشت کرلیا.یہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس کی اتباع یقیناً مومن کو اعلیٰ مراتب پر پہنچا سکتی ہے.قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ انہوں نے کہا (کہ) اے بادشاہ اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے (اسے اس کے صدمہ سے بچانے کے لئے) اس اَحَدَنَا مَكَانَهٗ١ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ۰۰۷۹ کی بجائے آپ ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لیجئے ہم آپ کو یقیناً محسنوں میں سے سمجھتے ہیں.حلّ لُغات.مَکَانٌ یُقَالُ ھٰذَا مَکَان ھٰذَا: اَیْ بَدَلُہٗ.(اقرب) جب ھٰذَا مَکَانُ ھٰذَا کہا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں یہ اس کی بجائے ہے.پس مکان کے معنے ہوئے بجائے.
Page 494
تفسیر.برادران یوسف کی سنگدلی سنگدلی کی حد ہو گئی.اول تو جھوٹا الزام بھائی پر چوری کا لگایا.پھر اس پر اس قدر غیرت جتاتے ہیں اور ایسی بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا وہ ان کا بھائی ہی نہیں.یہ نہیں کہتے کہ آپ اسے معاف فرمائیں کہ ہمارا باپ بڈھا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا باپ بڈھا ہے.گویا اس غیرت کی حالت میں اپنے آپ کو اس باپ کی اولاد ظاہر کرنے سے بھی شرماتے ہیں جس نے بن یامین اور یوسف جیسے بچے جنے تھے.قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا اس نے کہا(کہ ہم) اس بات سے اللہ (تعالیٰ) کی پناہ (چاہتے ہیں) کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے عِنْدَهٗۤ١ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَؒ۰۰۸۰ ہم اس کے سوا کسی (اور) کو پکڑیں.اس صورت میں ہم یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے( نہ کہ محسنوں میں سے).حلّ لُغَات.مَعَاذَاللہِ مَعَاذَاللہِ اَیْ اَعُوْذُبِاللہِ اَوْبِوَجْہِ اللہِ مَعَاذًا.مَعَاذَاللہِ کے معنے ہیں کہ (میں) اللہ کی پناہ (چاہتا ہوں).(اقرب) اَلْمَتَاعُ: سامان.مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت۲۴ و ہودآیت ۴.تفسیر.کفارہ کا ردّ اس آیت سے کفارہ کا بھی رد نکلتا ہے.یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بدلہ میں دوسرے کو رکھنا ظلم ہے حالانکہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیش کررہے تھے.عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح نے ہمارے لئے اپنی مرضی سے صلیب کو قبول کیا.اس لئے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوئے(The Jerom Biblica Commentary edited by Ramond E Brown ss vol 2 p.167).لیکن بائبل بھی اس قسم کے کفارہ کو ظلم قرار دیتی ہے.حضرت یوسف کا بن یامین کی جگہ کسی اور کو لینے سے انکار حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہی لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بن یامین کی جگہ ہم میں سے کسی کو قید کرلو تو یوسف علیہ السلام نے کہا ’’خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں.یہ شخص جس کے پاس سے میرا پیالہ نکلا وہی میرا غلام ہوگا.‘‘ (پیدائش باب ۱۷/۴۴) معلوم ہوا کہ بے گناہ کو گنہ گار کی جگہ پکڑ کر سزا دینا خواہ وہ بے گناہ راضی ہی کیوں نہ ہو
Page 495
بائبل کے نزدیک بھی ظلم ہے.فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا١ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ پس جب وہ اس سے( یعنی یوسف سے) ناامید ہو گئے تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے (لوگوں سے) الگ ہو گئے اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ (تب) ان میں سے بڑے نے کہا (کہ) کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے پکا قول لیا( ہوا) ہے جو اللّٰهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ١ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ اللہ(تعالیٰ کی قسم) سے (مؤکد )ہے اور یہ کہ( اس سے )پہلے تم یوسف کے بارہ میں( بھی) کوتاہی کر چکے ہو.اس الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ١ۚ وَ هُوَ لئے جب تک میرا باپ مجھے(خاص طور پر) اجازت( نہ) دے یا (خود)اللہ (تعالیٰ) میرے حق میں فیصلہ (کی خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ۰۰۸۱ کوئی راہ پیدا نہ )کرے میں اس ملک کو نہیںچھوڑوں گا.اور وہ( یعنی اللہ تعالیٰ) سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر (فیصلہ کرنے والا) ہے.حلّ لُغَات.اِسْتَیْئَسُوْا.یَئِسَ قَنَطَ وَاسَتَیْئَسَ بمعنے یَئِسَ.یَئِسَ اور اِسْتَیْئَسَ کے معنی ہیں بالکل مایوس و ناامید ہو گیا اور اِسْتَیْئَسُوْا.اِسْتَیْئَسَ سے جمع کا صیغہ ہے جس کے معنے ہوئے وہ ناامید ہو گئے.(اقرب) خَلَصَ اِلَیْہِ وَبِہِ الشَّیْءُ کے معنے ہیں وَصَلَ کہ کوئی چیز کسی تک پہنچی.(اقرب) پس خَلَصُوْا نَجِیًّا کے معنے ہوں گے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے کسی الگ جگہ پہنچے.اَلنَّجِیُّ.اَلسِّرُ.نَجِیٌّ کے معنی ہیں.راز.مَنْ تَسَارُہُ.رازدار.وَقَدْ یَکُوْنُ لِلْجَمْعِ اَیْضًا مِثْلَ الصَّدِیْقِ.یہ لفظ رازداروں کے معنے میں بھی استعمال ہوتا ہے.وَمِنْہُ خَلَصُوْا نَجِیًّا.اَیْ مُتَنَاجِیْنَ.اور خَلَصُوْا نَجِیًّا انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے راز کی باتیں کہتے ہوئے الگ ہوئے.قَالَ
Page 496
اَلنَّجِیُّ.اَلسِّرُ.نَجِیٌّ کے معنی ہیں.راز.مَنْ تَسَارُہُ.رازدار.وَقَدْ یَکُوْنُ لِلْجَمْعِ اَیْضًا مِثْلَ الصَّدِیْقِ.یہ لفظ رازداروں کے معنے میں بھی استعمال ہوتا ہے.وَمِنْہُ خَلَصُوْا نَجِیًّا.اَیْ مُتَنَاجِیْنَ.اور خَلَصُوْا نَجِیًّا انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے راز کی باتیں کہتے ہوئے الگ ہوئے.قَالَ الْفَرَّآءُ قَدْ یَکُوْنُ النَّجِیُّ وَالنَّجْوٰی اِسْمًا وَمَصْدَرًا اور فَرَّاء کے نزدیک نَـجِیٌّ اور نَـجْوٰی کا لفظ کبھی تو اسم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی مصدر کے معنوں میں.یعنی راز کی باتیں یا راز کی باتیں کرنا.اَلْمُحَدِّثُ راز کی باتیں کرنے والا.بات سنانے والا.اَلسَّرِیْعُ تیز.(اقرب) خَلَصُوْا نَجِیًّا.اَیْ اِنْفَرَدُوْا خَالِصِیْنَ عَنْ غَیْرِھِمْ خَلَصُوْا نَجِیًّا کے معنے ہیں دوسروں سے علیحدہ ہوئے.(مفردات) کَبِیْرُھُمْ.فُلَانٌ کَبِیْرٌ.اَیْ مُسِنٌّ.کَبِیْرٌ کے معنے ہیں عمر میں بڑا.اِنَّہٗ لَکَبِیْرُکُمْ اَیْ رَئِیْسُکُمْ اِنَّہٗ لَکَبِیْرُکُمْ کے معنے ہیں رفعت و منزلت کی رو سے بڑا سردار.(مفردات) اَلْمِیْثَاقُ.عَقْدٌ مُؤَکَّدٌ بِیَمِیْنٍ وَعَھْدٍ.میثاق کے معنے ہیں ایسا عہد کرنا جو قسم سے مؤکد ہو.وَالْمَوْثِقُ اَلْاِسْمُ مِنْہُ اور موثق کے معنے ہیں وہ عہد جو قسم سے مؤکد کیا گیا ہو.(مفردات) فَرَّطْتُّمْ.فَرَّطَ الشَّیْءَ وفَرَّطَ فِیْہِ.ضَیَّعَہٗ وَقَدَّمَ الْعَجَزَ فِیْہِ.فَرَّطَ جب بغیر صلہ کے یا فی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہو تو ا سکے معنے ہوتے ہیں کسی چیز کو ضائع کر دیاا ور اس کی حفاظت اور بچاؤ کے سامان سے پوری طرح کام نہ لیا.فَرَّطَ فِیْہِ.قَصَّرَ فِیْہِ.کوتاہی کی.(اقرب) اور فَرَّطْتُّمْ کے معنے ہوں گے تم نے کوتاہی کی.لَنْ اَبْرَحَ.لَنْ اَبْرَحَ مَابَرِحَ فُلَانٌ کَرِیْمًا.اَیْ بَقِیَ عَلَی کَرَمِہِ اَبْرَحُ.بَرِحَ سے مضارع متکلّم کا صیغہ ہے اور مَا بَرِحَ فلَانٌ کَرِیمًا کے معنے ہیں اپنی سخاوت پر قائم رہا.(اقرب) بَرِحَ اور زَالَمیں نفی کے معنے پائے جاتے ہیں بَرِحَ وَزَالَ اِقْتَضَیَا مَعْنَی النَّفْیِ وَلَا لِلنَّفْیِ وَالنَّفْیَانِ یَحْصُلُ مِنْ اِجْتِمَاعِھِمَا اِثْبَاتٌ.بَرِحَ اور زَالَ کے اندر نفی کے معنے پائے جاتے ہیں کیونکہ کسی جگہ سے چلے جانے کے مفہوم میں نہ موجود رہنا بھی داخل ہے جو نفی پر مشتمل ہے.پس جب ان پر مَا یا لَا وغیرہ کوئی کلمہ داخل ہوگا تو نفی پر نفی داخل ہونے کی وجہ سے ان میں اثبات کے معنے یعنی کسی جگہ پر موجود رہنے کے معنے پیدا ہوجاتے ہیں.(مفردات) پس لَنْ اَبْرَحَ کے معنے ہوںگے کہ میں اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا بلکہ وہیں رہوں گا.تفسیر.وہی بھائی جو مجلس میں یوسف پر چوری کا الزام لگا رہے تھے الگ ہوکر اپنے جرم کے شریکوں کے سامنے صاف اقرار کررہے ہیںکہ یوسفؑ کے بارہ میں ہم سے غلطی ہوئی تھی خدا کی شان ہے یوسف علیہ السلام ایسے مرتبہ پر فائز تھے کہ بھائیوں کے لئے ان کا پہچاننا ناممکن ہو گیا تھا.ورنہ یہ جانتے ہوئے کہ یہی یوسفؑ ہے وہ کب ا
Page 497
اس جھوٹ کے مرتکب ہوسکتے تھے.بڑے بھائی کے دل میں خشیت اللہ تھی كَبِيْرُهُمْ جس بھائی کی نسبت آیا ہے معلوم ہوتا ہے اس کے دل میں کسی قدر خشیت اللہ تھی.کیونکہ ایک تو وہ اپنے باپ سے غداری کرنے سے بھائیوں کو ڈراتا ہے دوسرے اپنے عہد کی پابندی پر مصر ہوا ہے کہ جب تک میرا باپ اجازت نہ دے یا خدا تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ کردے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا.خدا تعالیٰ کے فیصلہ سے مراد ہوسکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ ہو کہ کسی طرح بن یامین آزاد ہو جائیں اور میں ان کو ساتھ لے کر واپس چلا جاؤں.حضرت یوسف کے سب سے بڑے بھائی کا نام روبن تھا اور بائبل کی رو سے جس بھائی نے اس موقع پر گھر واپس جانے سے انکار کیا ہے وہ یہودا تھے(پیدائش باب ۲۹ و ۴۴) جو بھائیوں میں سے چوتھے درجہ پر تھے.مسیحی مصنفین کا اعتراض لفظ ’’کبیر‘‘ پر مسیحی مصنف اس جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کے مصنف کو تاریخ کا بھی علم نہیں(A Comprehensive Commentary on Holy Quran by Wherry under verse 80 chapter 12).وہ یہودا کی بات کو روبن کی طرف منسوب کررہا ہے.مجھے مسیحی مصنفوں کے ایسے اعتراضوں پر ہمیشہ تعجب آیا کرتا ہے.وہ یوں بائبل کا ذکر کرتے ہیں گویا وہ سب سے زیادہ مستند تاریخی کتاب ہے.بائبل کی شہادت سے قرآن کریم پر اعتراض نہیں ہوسکتا حالانکہ خود مسیحی لٹریچر ان دلائل سے بھرا پڑا ہے جو تاریخی طورپر بائبل کے رتبہ کو بہت گرا دیتے ہیں.پرانی تاریخ تو الگ رہی موسیٰ ؑ کی کتب میں موسیٰ کے سفروں کے جو حالات درج ہیں مسیحی محققین خود ان کی صحت کے قائل نہیں اور جغرافیہ اور اس زمانہ کی دوسری تاریخوں سے اور خود بائبل کی اندرونی شہادتوں سے ان حالات کو خلاف واقع ظاہر کرتے ہیں.ایسی کتاب کی روایت پر قرآن کریم پر اعتراض قابل تعجب ہے.ہم بے شک بائبل کی بعض روایات کو تاریخی شہادت کے طور پر نقل کرتے ہیں لیکن اسی وقت جبکہ وہ عقل اور دوسری تاریخ یا قرآن کریم کے مطابق ہوں ورنہ بائبل میں اس قدر دست برد ہوچکی ہے کہ اس کی تاریخ بھی محفوظ نہیں کہی جاسکتی.پس ان حالات میں بائبل کی شہادت پر قرآن کریم پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا جس کے یہودی تاریخ کے بتائے ہوئے واقعات اس وقت تحقیق سے صحیح ثابت ہورہے ہیں جبکہ یہودی تاریخ کے بیانات غلط ثابت ہو رہے ہیںمثلاً ہارون کا بچھڑے کو پوجنا.فرعونِ موسیٰ ؑ کی لاش کا محفوظ رہنا وغیرہ.قرآن کریم میں کَبِیْرُھُمْ ہے نہ کہ اَکْبَرُھُمْ لیکن اگر ہم اس بارہ میں توریت کے بیان کو صحیح سمجھ
Page 498
لیں تو بھی کوئی اعتراض نہیں پڑتا.اس لئے کہ قرآن کریم نے کَبِیْرُھُمْ کہا ہے اَکْبَرُھُمْ نہیں کہا.بارہ بیٹوں میں سے چوتھا بیٹا بھی یقیناً کبیر کہلاسکتا ہے.کیونکہ کبیر کے معنے صرف بڑے کے ہیں نہ کہ سب سے بڑے کے.قرآن مجید اور بائبل کے بیان میں تطبیق اس کے علاوہ یوں بھی بائبل کے بیان اور قرآن مجید کے بیان میں تطبیق دی جاسکتی ہے کہ کبیر سے مراد عمر میں بڑا نہ لئے جائیں بلکہ درجہ میں بڑے کے لئے جائیں.چنانچہ زیر آیت قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ الخ ۶۶میں ثابت کر آیا ہوں کہ حضرت یعقوب کو جو اعتبار یہودا پر تھا روبن پر نہ تھا.بن یامین کو انہوں نے بھیجا بھی یہودا کی ضمانت پر تھا.پس اس معاملہ میں یہودا ہی سب سے بڑے تھے.اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ١ۚ وَ تم اپنے باپ کی طرف( لوٹ) جاؤ اور( اس سے جاکر) کہو (کہ) اے ہمارے باپ آپ کے (چھوٹے )بیٹے مَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ۰۰۸۲ نے ضرور چوری کی ہے.اور ہم نے( آپ سے) سوائے اس بات کے جس کا ہمیں (ذاتی) علم ہے (قطعاً) کچھ نہیں کہا.اور ہم( اپنی) نظر سے پوشیدہ بات کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے.تفسیر.اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ حضرت یوسف کا قول نہیں بعض مفسرین نے اس قول کو یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے.یہ تفسیر میری سمجھ سے باہر ہے.عبارت کا ربط بھی ان معنوں کے خلاف ہے میرے نزدیک تو یہ اس بڑے بھائی کا قول ہے جس کا قول اس سے پہلے درج ہوا ہے.مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ وَ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ کے ایک معنے تو یہ ہیں کہ ہمیں پوری واقفیت نہیں ہم نے ظاہر میں جو کچھ دیکھا اسے بیان کر دیا.ہم غیب سے واقف نہیں.دوم یہ کہ یہ فقرہ عہد کے متعلق ہو کہ جب ہم نے عہد کیا تھا اس وقت ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ہم ایسی خبر تیرے پاس لائیں گے.ہم نے اس وقت عہد دیانت داری سے ہی کیا تھا.
Page 499
وَ سْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا اور آپ (بے شک) ان لوگوں سے( بھی) دریافت کر لیں جن میں ہم (رہتے) تھے اور اس قافلہ سے (بھی) جس فِيْهَا١ؕ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ۰۰۸۳ کے ساتھ ہم آئے ہیں اور یقین جانیئے کہ ہم( اس بات میں) سچے ہیں.حلّ لُغَات.اَلْقَرْیَۃُ اَلْقَرْیَۃُ اِسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِیْ یَجْتَمِعُ فِیْہِ النَّاسُ.قریہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں.وَلِلنَّاسِ جَمِیْعًا اور جمع شدہ لوگوں کو بھی قریہ کہتے ہیں.وَیُسْتَعْمَلُ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْہُمَا.اور قریہ ان ہر دو معنے میں استعمال ہوتا ہے.قَالَ تَعَالٰی وَسْئَلِ الْقَرْیَۃَ قَالَ کَثِیْرٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِیْنَ مَعْنَاہُ اَھْلَ الْقَرْیَۃِ مذکورہ بالا آیت میں وَسْئَلِ الْقَرْیَۃَ کے معنے اکثر مفسرین نے اَھْلِ قَرْیَۃ ’’یعنی بستی کے رہنے والے‘‘ کئے ہیں.وَقَالَ بَعْضُھُمْ بَلِ الْقَرْیَۃُ ھٰھُنَا اَلْقَوْمُ اَنْفُسُھُمْ اور بعض مفسرین نے یوں کہا ہے کہ قریۃ سے مراد خود لوگ ہی ہیں اہل قریہ نہیں.(مفردات) (مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت۹۵) تفسیر.یہ قول اسی بھائی کا ہے جو اپنے والد کے پاس جاکر جو کچھ کہنا چاہیے اس کی تلقین کررہا ہے.صداقت انسان کا لہجہ بدل دیتی ہے صداقت کس طرح انسان کا لہجہ ہی بدل دیتی ہے.وہی بھائی یوسفؑ کی دفعہ فریب کرکے آئے تو کس طرح اپنی بات پر زور دینے سے ہچکچاتے تھے لیکن اب جو بن یامین کی خبر دینے چلے ہیں تو کس زور سے اپنے سچے ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور گواہ بھی پیش کرتے ہیں.قَریہ اور عِیر سے مراد اہل قَریہ اور اَصحابُ الْعِیر ہے اس جگہ اہل مصر کو قریۃ کے نام سے اور قافلہ والوں کو عیر کے نام سے یاد کیا ہے.حالانکہ عِیْر گدھوں کو کہتے ہیں ایسا انہوں نے اپنی بات پر زور دینے کے لئے کیا.اصل میں اَھْلُ الْقَرْیَۃِ وَاَصْحَابُ الْعِیْرِ ہے.مگر ’’اصحاب‘‘ کا لفظ اڑا دیا اور یہ عربی کا عام دستور ہے.توجہ کھینچنے کے لئے ایسا کرتے ہیں.مطلب یہ کہ شہر کا بچہ بچہ اور قافلہ کا فرد فرد اس حقیقت سے آگاہ ہے.آپ کسی سے پوچھ کر دیکھ لیں وہ ہماری تصدیق کرے گا.
Page 500
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا١ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ١ؕ اس نے( یعنی یعقوبؑ نے) کہا (کہ یہ بات درست )نہیں(معلوم ہوتی) بلکہ (معلوم ہوتا ہے کہ) تمہارے عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا١ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ نفسوں نے کوئی بات خوبصورت کر کے تمہیں دکھائی ہے (اور اس کے تم مرتکب ہوئے ہو) پس( اب میرا کام تو) الْحَكِيْمُ۰۰۸۴ اچھی طرح صبر کرنا(ہی) ہے (کچھ) بعید نہیں کہ اللہ( تعالیٰ) ان سب کو میرے پاس لے آئے.یقیناً وہی ہے جو خوب جاننے والا (اور) حکمت والا ہے.حل لغات.سَوَّلَتْ سَوَّلَتْ لَہٗ نَفْسُہٗ کَذَا زَیَّنَتْہُ لَہٗ وَسَھَّلَتْہُ لَہٗ وَھَوَّ نَتْہُ اس کے نفس نے اس کے لئے اس کام کو خوبصورت کرکے یا اسے ایک معمولی بات قرار دے کر اور آسان کرکے دکھایا.(اقرب) اَلتَّسْوِیْلُ تَزْیِیْنُ النَّفْسِ لِمَا تَحْرِصُ عَلَیْہِ وَتَصْوِیْرُ الْقَبِیْحِ مِنْہُ بِصُوْرَۃِ الْحَسَنِ جس بات کی طرف میلان ہو اسے نفس کا پسندیدہ کرکے دکھانا اور بری بات کو اچھے رنگ میں پیش کرنے کا نام تَسْوِیل ہے.(مفردات) پس سَوَّلَتْ کے معنے ہوں گے کہ تمہارے نفسوں نے کوئی بات خوبصورت کرکے تمہیں دکھائی ہے.تفسیر.یہاں قرآن کریم کے طریق کے مطابق اس ذکر کو چھوڑ دیا ہے کہ پھر بھائی آئے اور انہوں نے اپنے والد کو یہ باتیں کہیں بلکہ والد کا جواب بیان کر دینا شروع کر دیا ہے.قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں.وہ زائد باتیں چھوڑ دیتا ہے.اس جگہ اس درمیانی بات کو چھوڑ دینے کی غرض یہ ہے کہ جو سبق دیا جارہا ہے اس میں وقفہ نہ پڑے اور پڑھنے والے کا ذہن سیدھا اس مضمون کی طرف منتقل ہو جو اس کے سامنے پیش کیا جارہا ہے.برادران بن یامین نے دشمنی کے باعث اس کی طرف چوری کا عیب منسوب کردیا حضرت یعقوبؑ نے بیٹوں کی باتیں سن کر کہا کہ اصل میں تمہارے نفس کی خواہشات نے بری بات کو اچھا کر دکھایا ہے.اس کا یہ مطلب نہیں کہ بن یامین روکا نہیں گیا اور تم جھوٹ بولتے ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ بن یامین کی دشمنی کی وجہ سے تمہارا ذہن ادھر نہیں گیا کہ وہ چوری کا مرتکب نہیں ہوسکتا.ضرورا س واقع میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور تم نے اس سے دشمنی رکھنےکے باعث فوراً اس کی طرف اس عیب کو منسوب کر دیا ہے.
Page 501
یہودا کے اپنے قول پر قائم رہنے کا حضرت یعقوب پر اثر یہ کہہ کر کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یوسف بھی اب تک زندہ ہے اور شاید خدا تعالیٰ یوسفؑ اور بن یامین اور یہودا سب کو واپس لے آوے.اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودا کے اپنے قول پر قائم رہنے کا نیک اثر حضرت یعقوبؑ کے دل پر ہوا ہے اور اس کی نسبت بھی ان کے دل میں درد پیدا ہونے لگ گیا ہے.وہ بہت جانتا اور بہت حکمت والا ہے.اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر حقیقت کھول دی ہے اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کیا ہمارے فائدہ ہی کے لئے کیا.گذشتہ تکلیف درحقیقت ہمارے خاندان کی آئندہ ترقی کا ایک پیش خیمہ تھی.وَ تَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَ ابْيَضَّتْ اور اس نے ان کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا.اور( الگ جا کر دعا کی اور) کہا اے( میرے خدا!) یوسف پر میرے عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ۰۰۸۵ (اس) غم (و اندوہ کا سلسلہ کب ختم ہو گا) اور غم کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سفیدی آگئی.مگر وہ اپنے غم کو( ہمیشہ اپنے دل کے) اندر (ہی )دبائے رکھتا تھا.حلّ لُغَات.تَوَلّٰی عَنْہُ.تَوَلّٰی عَنْہُ اَعْرَضَ وَتَرَکَہٗ تَوَلّٰی عَنْہُ کے معنے ہیں رخ پھیر لیا اور چھوڑ دیا.(اقرب) یَا اَسَفٰی یَا اَسَفٰی وَیَااَسَفَاعَلٰی کَذَا تَوَجُّعٌ وَتَحَسُّرٌ عَلٰی مَافَاتَ کسی چیز کے ضائع ہونے پر دکھ اور درد کا اظہا رکرنے کے لئے یَا اَسَفٰی کے الفاظ بولے جاتے ہیں.(اقرب) اِبْیَضَّتْ عَیْنٰہُ یُقَالُ لِلْمَھْمُوْمِ اَظْلَمتْ عَلَیْہِ الدُّنْیَا وَابْیَضَّتْ عَیْنٰہُ مِنَ الْحُزْنِ (مجمع البحار جلد دوم ۴۴۹) جو غمزدہ ہو اس کے متعلق عرب یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ دنیا اس پر تاریک ہوگئی ہے اور یہ بھی کہ غم سے اس کی آنکھیں سفید ہوگئی ہیں.اَلْحُزْنُ.خُشُوْنَۃٌ فِی النَّفْسِ لِمَا یَحْصُلُ فِیْہِ مِنَ الْغَمِّ.دل کی بے قراری جو غم کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے.وَیُضَادُّہُ الفَرَحُ اور اس کے بالمقابل فَرَحٌ کا لفظ بولا جاتا ہے.(مفردات)
Page 502
اَلْکَظِیْمُ الْکُظُوْمُ النَّفَسِ اِحْتِبَاسُ النَّفَسِ.کُظُوْمٌکے معنے ہیں سانس کا رکنا.وَیُعَبَّرُ بِہٖ عَنِ السُّکُوْتِ.خاموشی کے موقعہ پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے.کَظَمَ الْغَیْظَ.حَبَسَہٗ.غیظ کے ساتھ جب کَظَمَ کا لفظ آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں غصہ کو روک لیا.کَظَمَ السِّقَاءَ شَدَّہٗ بَعْدَ مِلْئِہِ مَانِعًا لِنَفْسِہِ.اور جب سِقَاء کے لئے کَظَمْ کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں مشکیزہ بھر کر پانی کو محفوظ رکھنے کے لئے اس کا منہ بند کر دیا.پس کَظِیْمٌ ایسے شخص کو کہیں گے کہ جو اپنے اندر غصہ کو دبائے رکھے اور ظاہر نہ ہونے دے.(مفردات) تفسیر.اِبْيَضَّتْ عَيْنٰهُ کے معنوں میں مفسرین کا اختلاف اِبْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ.غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں.اس کے متعلق بڑا اختلاف ہوا ہے.مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی ہوگئی تھیں اور ان پر سفیدی ہی سفیدی چھا گئی تھی.اس کے متعلق ان میں اختلاف ہے کہ سفیدی کیوں چھا گئی.بعض نے کہا ہے کہ روتے روتے اور اس رونے کی مدت بعض نے چالیس سال اور بعض نے ۸۱ سال بیان کی ہے.بعض کہتے ہیں کہ دوسرے بیٹے کی خبر سن کر صدمہ سے بینائی جاتی رہی کہ اب تو دوسرا بھی جدا ہو گیا(تفسیر فتح البیان زیر آیت ھٰذا).دراصل اِبْیَضَّ کے ایک معنے بھی ایسے نہیں کہ جن سے اندھا ہونے کا مفہوم نکل سکے.صرف ایک معنوں کو کھینچ تان کر یہ مفہوم نکالا گیا ہے.بَیَّضَ کے معنے عربی میں کہتے ہیں کہ بَیَّضَ السِّقَاءَ.مشکیزہ کو دودھ یا پانی سے بھر دیا.یہ معنی جوہر اور صاغانی نے لکھے ہیں.اسی طرح کہتے ہیں بَیَّضَہٗ مشکیزہ کو خالی کر دیا.گویا یہ لفظ اَضْدَاد معنے رکھتا ہے.یہ امر صاغانی اور لسا ن العرب نے بیان کیاہے اور تاج العروس والا کہتا ہے کہ یہ مجازی معنے ہیں عام معنی اِبْیَضَّ اور اِبْیَاضَّ کے اِسْوَدَّ اور اِسْوَادَّ کے خلاف ہیں یعنی جس طرح اِسْوَدَّ اور اِسْوَادَّ کے معنی سیاہ ہونے کے ہیں.اِبْیَاضَّ کے معنے اِبْیَضَّ اور اِبْیَاضَّ کے معنی سفید ہونے کے ہیں اور اِبْیَضَّ اور اِبْیَاضَّ کبھی بَیَّضَ کا مُطَاوِع ہوکر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی سفید ہو گیا.اب اس آخری بات سے بعض نے یہ معنی نکالے ہیں کہ چونکہ بیّض کے معنی مجازاً خالی کر دینے کے ہیں جیسے کہ لسان العرب میں آیا ہے اور چونکہ اِبْیَضَّ بَیَّضَ کا مطاوع ہوکر استعمال ہو جاتا ہے.اس لئے وہ مجازی معنے بَیَّضَ کے یہاں اِبْیَضَّ میں بھی آسکتے ہیں.اس لئے انہوں نے اِبْیَضَّتْ عَیْنٰہُ کے معنے یہ کئے ہیں کہ اس کی آنکھیں غم کے مارے بہ پڑیں اور خالی ہو گئیں.اور بعض مفسرین نے سفید ہونے سے بھی اندھا ہونا مراد لیا ہے.
Page 503
اِبْیَضَّ کے معنے لغت میں اندھا ہونے کے نہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ جب اِبْیَضَّکے معنے لغت میں اندھا ہونے کے نہیں ہیں تو کیوں نہ اِبْیَضَّتْ کے معنے پانی سے بھر جانے کے کئے جاویں.جبکہ پانی اور دودھ کو اَبْیَضَانِ کہنے کا محاورہ عربی میں مستعمل ہے.اور ظاہر ہے کہ آنکھوں میں پانی بھر آنے کا یہی مطلب ہے کہ آنسو بھر آئے اور دوسرے معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑیں یعنی کثرت سے آنسو ٹپک پڑے.اِبْیَضَّ کے مجازی معنے آنکھوں کے غم سے چمک پڑنے کے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر اِبْیَضَّتْ سے ہم نے مجاز ہی لینا ہے تو کیوں نہ وہ مجاز لیں جو اعلیٰ ہو.یعنی یہ کہ غم کے مارے ان کی آنکھیں چمک پڑیں اور یہ ایک قدرتی بات ہے کہ غم کے وقت انسان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ وہ غم دیر تک نہ لگا رہے.ادیب بھی ان معنوں میں آنکھوں میں چمک پیدا ہونے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ادیب لوگ بھی اس غم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے جس میں ابھی امید کی جھلک باقی ہو آنکھوں میں چمک پیدا ہونے کے الفاظ استعمال کرلیا کرتے ہیں.تو گویا جب تازہ غم میں جس میں امید کی شعاع نظر آتی ہو جب ایک جھلک اور چمک آنکھوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو کیوں نہ یہ معنے کئے جائیں کہ ان کی آنکھیں اس تازہ غم کی وجہ سے چمک اٹھیں کیونکہ انہوں نے محسوس کرلیا کہ غم اپنی انتہاء کو پہنچ گیا ہے اور اب ضرور خدا تعالیٰ کا فضل نازل ہوگا.اِبْيَضَّتْ عَيْنٰهُ کے معنے شدید غم میں مبتلا ہونے کے ہیں مگر جیسا کہ حل لغات کے نیچے لکھا گیا ہے اِبْیَضَّتْ عَیْنٰہُ مِنَ الْحُزْنِ کے معنے شدید غم میں مبتلا ہونے کے بھی ہوتے ہیں.پس ان معنوں کی موجودگی میں اور معنی کرنا صرف عجوبہ پسندی ہی کہلا سکتا ہے جس کا قرآن کریم محتاج نہیں.کَظِیْمٌ کا لفظ رو رو کر اندھا ہونے کو ردّ کرتا ہے اور جبکہ اس کے معاً بعد اللہ تعالیٰ نے فَهُوَ كَظِيْمٌ کے الفاظ استعمال کئے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے غم کو دبانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے رو رو کر آنکھیں ضائع کردیں.رو رو کر آنکھیں کھو دینے والے کو کوئی غم دبانے والا نہیں کہہ سکتا.اس لفظ کی موجودگی میں تو اگر اِبْیَضَّ کے معنے رو رو کر اندھا ہونے کے لغت میں ہوتے بھی تب بھی وہ اس جگہ چسپاں نہ ہوسکتے تھے.صَبْرٌ جَمِيْلٌ علاوہ ازیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا قول قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا
Page 504
فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ میں اعلیٰ درجہ کے صبر کا نمونہ دکھاؤں گا.اگر رو روکر انہوں نے آنکھیں ضائع کردی تھیں تو اعلیٰ درجہ کے صبر کا نمونہ دکھانے کا وہ کیونکر دعویٰ کرسکتے تھے؟ صبر کا مفہوم ایک حدیث سے.آنحضور ؐ کے گیارہ بچے فوت ہوئے صبر کا مفہوم ایک حدیث سے اچھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے.روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے بیٹے کی قبر پر روتے دیکھا تو فرمایا کہ صبر کرو.عورت نے جواب دیا کہ اگر تیرا بیٹا فوت ہوجاتا تو کیسے صبر کرتا.معلوم ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوا کہ اسے نصیحت کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ میرے تو گیارہ بچے فوت ہوچکے ہیں اور میں نے صبر کیا ہے.یہ کہہ کر حضور چلے گئے.بعدمیں جب لوگوں نے اسے ملامت کی کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نامناسب جواب دیا تو وہ نادم ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ یارسول اللہ! میں نے آپؐ کو پہچانا نہ تھا.میں نے اب صبر کیا.تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَاالصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَۃِ الْأُوْلٰی صبر تو مصیبت کے پہلے صدمہ کے موقع پر ہوتا ہے (بخاری کتاب الجنائز باب زیارۃ الصبور).بعد میں تو سب ہی خاموش ہوجاتے ہیں.پس جب چند گھنٹے رو دھو کر خاموش ہوجانے سے بھی انسان بے صبر کہلا سکتا ہے تو چالیس سال رونے والا کس منہ سے صبر کا اور پھر صبر جمیل کا دعویٰ کرسکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ غم کی کیفیت کو ایسا لمبا کرنا جو انسان کو ناکارہ کردے خواہ اس غم کا لوگوں پر اظہار ہو یا نہ ہو اسی کا نام جزع فزع ہے جو ناپسندیدہ ہے.اور نبی کی شان سے بالکل بعید ہے کہ کسی بات پر وہ اس قدر غم کرے کہ اس کی ہلاکت کا مترادف ہو.اگر وہ روتے رہتے تھے تو دین کی خدمت کس طرح کرتے تھے؟ پس مجازی معنوں کی صورت میں بھی وہ معنے لینے چاہئیں جو حضرت یعقوبؑ کی شان کے مطابق ہوں نہ وہ جو انہیں عام مومن کے درجہ سے بھی گرا دیں.
Page 505
قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ انہوں نے کہا( کہ) اللہ کی قسم (یوں معلوم ہوتا ہے کہ) آپ یوسف کا ذکر کرتے ہی رہیں گے.یہاں تک کہ آپ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ۰۰۸۶ بیمار پڑ جائیں یا آپ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہو جائیں.حلّ لُغَات.مَافَتِیَٔ مَافَتَأَ یَفْعَلُ کَذَا.وَمَافَتِیَٔ اَیْ مَازَالَ.مَافَتِیَٔ کے معنے ہیں کوئی کام لگاتار کرنا اور اس کا سلسلہ نہ توڑنا (اقرب) اور تَفْتَؤُاتَذْکُرُ کے معنی ہوں گے کہ آپ ذکر کرتے ہی رہیں گے.حَرَضٌ.حَرَضَ حُرُوْضًا کَانَ مُضْنًا مَرَضًا وَسُقْمًا.حَرَضَ کے معنی ہیں بیماری کی وجہ سے لاغر ہو گیا.الرَّجُلُ نَفْسَہٗ اَفْسَدَھَا اپنی حالت کو خراب کرلیا.حَرِضَ حَرَضًا: فَسَدَ بَدَنُہٗ لَایَقْدِرُ عَلَی النُّہُوْضِ: جب اس کا مصدر حَرَضًا آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں بدن اتنا کمزور ہو گیا کہ حرکت کے قابل نہ رہا اور حَرُضَ حَرَاضَۃً کے معنے ہیں طَالَ ھَمُّہٗ غم لمبا ہو گیا.اَلْحَرْضُ اَلْفَسَادُ فِی الْبَدَنِ وَفِی الْمَذْھَبِ وَفِی الْعَقْلِ.بدن، مذہب یا عقل میں کسی خرابی کے پیدا ہوجانے کو حَرَضٌ کہتے ہیں اَلْمُشْرِفُ عَلَی الْھَلَاکِ تَسْمِیَۃً بِالمَصْدِرِ لِلمُبَالَغَۃِ اور ہلاکت کے کنارہ پر پہنچے ہوئے شخص کو بھی حَرَضٌ کہتے ہیں.مصدر مبالغہ کے لئے استعمال ہوا ہے.جیسے کہتے ہیں زَیْدٌ عَدْلٌ کہ زید تو مجسمہ عدل ہے.حَرَضٌ کے اور بھی کئی معانی ہیں مثلاً مَنْ لَاخَیْرَ عِنْدَہٗ وَقِیْلَ مَن لَا یُرْجٰی خَیْرُہٗ وَلَایُخَافُ شَرُّہٗ جس سے نہ تو کسی بھلائی کی امید ہو اور نہ ہی کسی تکلیف کا خطرہ ہو.مَنْ اَذَابَہُ الْحُزْنُ اَوِالْعِشْقُ جس کو غم یا عشق گھلا دے.السَّاقِطُ لَاخَیْرَ فِیْہِ.نکما.اَلرَّدِیُٔ مِنَ النَّاسِ ناکارہ شخص.المُضْنٰی مَرَضًا وَسُقْمًا وَمِنْہُ فِی الْقُراٰنِ حَتّٰی تَکُوْنَ حَرَضًا اَیْ مُدْنَفًا.بیماری کی وجہ سے لاغر اور انہی معنوں میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.(اقرب) تفسیر.لَاتَفْتَؤُا استمرار و نفی کے لئے آتا ہے لَاتَفْتَؤُا استمرار و نفی کے لئے آتا ہے اور لَایَزَالُ کے معنوں میں آتا ہے کبھی بغیر قسم کے استعمال ہوتاہے کبھی وہ ساتھ ملحوظ ہوتی ہے.یعنی تو ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے گا یہاں تک کہ تو کمزور ہو جائے گا.تو حَرَضٌ کے معنے بالکل نکما یا ہلاک ہونے کے ہوئے.یوسفؑ کے بھائی تو اعتراض کرتے ہیں کہ تو اس طرح نکما ہو جائے گا مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ
Page 506
حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہوکر نکمے ہو گئے تھے وہ گویا کہتے ہیں کہ وہ اس خطرہ کے اظہار سے پہلے ہی نکمے ہوچکے تھے.حالانکہ خدا تعالیٰ کے نبی ہمیشہ صبر کرتے ہیں اور اس طرح گھبراتے نہیں.ہم نے خود ایک نبی کو دیکھا ہے اور اس کے حالات کو بھی دیکھا ہے.قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَ حُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ اس نے کہا( کہ) میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ (تعالیٰ) ہی کے حضور کر تا ہوں اور میں اللہ( تعالیٰ) کی طرف مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۰۰۸۷ سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے.حلّ لُغَات.اَلْبَثُّ اَلْحَالُ.بَثٌّ کے معنے ہیں حال.اَشَدُّ الْحُزنِ.سخت غم.(اقرب) اَصْلُ الْبَثِّ اَلتَّفْرِیْقُ وَاِثَارَۃُ الشَّیءِ.بَثّ کے اصل معنے بکھیرنے اور منتشر کرنے کے ہیں.وَبَثُّ النَّفْسِ مَاانْطَوَتْ عَلَیْہِ مِنَ الْغَمِّ وَالسِّرِّ.اور بَثُّ النَّفْسِ کے معنے ہیں غم اور راز.اِنَّمَا اَشْکُوْا بَثِّی اَیْ غَمِّیَ الَّذِیْ یَبُثُّہٗ عَنْ کِتْمَانٍ اِنَّمَا اَشْکُوْا بَثِّیْ کے معنے ہیں کہ میں اپنے اس غم کی فریاد کرتا ہوں جس کا اظہار کئے بغیر کوئی چارہ نہیں.غَمِیَّ الَّذِیْ بَثَّ فِکْرِیْ.ایسا غم جس نے فکر اور سوچ کی طاقت کو پراگندہ کر دیا ہو.(مفردات) تفسیر.حضرت یعقوبؑ کو یوسف کے زندہ ہونے کا علم دیا گیا تھا میں تو اپنی حالت اور غم کی شکایت صرف اللہ کے پاس کرتا ہوں وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ اور میں اس کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.اس میں اشارہ ہے کہ ان کو حضرت یوسفؑ کے زندہ ہونے کا علم خداوند تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا ہوا تھا.يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَ اَخِيْهِ وَ لَا اے میرے بیٹو! جاؤ اور( جا کر) یوسف اور اس کے بھائی کی جستجو کرو تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ١ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اور اللہ( تعالیٰ) کی رحمت سے ناامید مت ہو (اصل) بات یہی ہے کہ اللہ( تعالیٰ) کی رحمت سے کافر لوگوں کے
Page 507
اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ۰۰۸۸ سوا کوئی (انسان) نا امید نہیں ہوتا.حلّ لُغَات.تَحَسَّسُوْا.تَحَسَّسَ اِسْتَمَعَ لِحَدیْثِ الْقَوْمِ:- تَحَسَّسَ کے معنے ہیں قوم کی باتوں کو غور سے سنا.وَطَلَبَ خَبَرَھُمْ فِی الْخَیْرِ اور ان کی اچھی بات کی جستجو کی.وَقِیْلَ التَّحَسُّسُ شِبْہُ التَّسَمُّعِ وَالتَّبَصُّرِ اور بعض نے یوں بیان کیا ہے کہ تَحَسَّسَ کے معنوں میں ویسا ہی زور پایا جاتا ہے جیسے تَسَمُّعٌ اور تَبَصُّرٌ کے معنوں میں.یعنی کسی چیز کو غور سے سننا اور دیکھنا.چنانچہ مثال کے طور پر اُخْرُجْ فَتَحَسَّسْ لَنَا کا فقرہ ہے جس کے معنے ہیں کہ اے مخاطب جا اور جاکر مطلوبہ چیز کو اپنے حواس سے اچھی طرح طلب کر یعنی خوب غور سے اس کی جستجو کر.وقال ’’ اَ بُوْعُبَیْدٍ تَحسَّسْتُ الْخَبَرَ وتَحَسَّیْتُ‘‘ اور ابوعبید نے کہا ہے کہ تَحَسَّسْتُ اور تَحَسَّیْتُ جس کے معنے کسی چیز کو حواس سے طلب کرنے کے ہیں ہم معنے ہیں.مِنَ الشَّیْءِ تَخَبَّرَ خَبَرَہٗ.تَحسَّسْتُ مِنَ الشَّیْ ءِکے معنے ہیں کہ کسی خبر کی جستجو کی.وَبِکُلِّ مَاذُکِرَ فُسِّرَ قَوْلُ الْقُراٰنِ.یٰبُنِیَّ اذْھَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ یُوسُفَ وَاَخِیْہِ.مذکورہ بالا سارے معنے آیت فَتَحَسَّسُوْا میں چسپان ہوسکتے ہیں.(اقرب) لَاتَایْئَسُوْا: یَئِسَ قَنَطَ اَوْقَطَعَ الْاَمْلَ.فَہُوَ یَائِسٌ یَئِسَ کے معنے ہیں ناامید ہو گیا یا امید کو چھوڑ دیا اور ایسے شخص کو یَائِسٌ کہتے ہیں.(اقرب) وَلَا تَایْئَسُوْا کے معنے ہوں گے تم ناامید نہ ہو.رَوْحٌ.رَاحَ.رَوْحًا.ذَھَبَ اِلَیْھِمْ فِی الرَّوَاحِ.رَوْحٌ رَاحَ کا مصدر ہے.اور رَاحَ کے معنے ہیں کسی کے پاس شام کو گیا.رَا حَ الْیَوْمُ.اِذَا کَانَ رَیْحًا طَیِّبًا.رَاحَ الْیَوْمُ کے معنی ہیں ہوا والا خوشگوار دن.وَالرَّوْحُ بِمَعْنَی الرَّاحَۃِ اور روح کے معنے ہیں راحت.وَنَسِیْمُ الرِّیْحِ تَقُوْلُ وَجَدْتُ رَوْحَ الشَّمَالِ.بادنسیم اور انہی معنوں میں وَجَدْتُ رَوْحَ الشَّمَالِ کا فقرہ استعمال ہوا ہے کہ میں نے شمال کی طرف سے بادنسیم کو محسوس کیا.وَالنُّصْرۃُ مدد.وَالْعَدْلُ الَّذِیْ یُرِیْحُ الْمُشْتَکیْ ایسا عدل جو شکایت کرنے والے کو تسلی دے دے.وَالْفَرَحُ.وَالسُّرُوْرُ خوشی وَالرَّحْمَۃُ.رحمت.وَمِنْہُ لَاتَایْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللہِ.اور اس آیت میں یہی آخری معنے مراد ہیں.(اقرب) تفسیر.اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے اور پھر مصر میں ہونے کی خبر خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل تھی ورنہ ممکن نہیں ایک لڑکے کے متعلق جسے وہ سمجھتے
Page 508
ہوں کہ بھیڑیا کھا گیا ہے یا اور کسی ذریعہ سے مر چکا ہے وہ اپنے بیٹوں کو تلاش کا حکم دیتے اور خصوصاً مصر میں تلاش کا حکم دیتے.ترقی کا بے عدیل گر.تمام ناکامیوں کی جڑ ہمت ہارنا ہے اس آیت میں روحانی اور جسمانی ترقی کا بے عدیل گر بتایا ہے.تمام ناکامیوں کی جڑ ہمت ہار دینا ہے.جو شخص قطعی اور یقینی علم کے بغیر کام ترک کر دیتا ہے ہمیشہ اپنے پیشہ میں یا اپنے مقصد میں ناکام رہتا ہے.معمولی سے معمولی پیشوں میں بھی یہ اصل کام دے رہا ہے.ایک بڑے آہن گر اور ایک معمولی آہن گر میں یہی فرق دیکھو گے کہ ایک ہر مشکل کام کے وقت کہے گا یہ نہیں ہوسکتا دوسرا اس کے حل کرنے پر لگا رہے گا.اور آخر کامیاب ہو جائے گا.پیشوں میں ہی نہیں قدرت کے افعال میں بھی یہ اصل کام کررہا ہے.جو بیمار صحت کی امید دل سے نکال دیتا ہے اسے صحت ہونی مشکل ہوجاتی ہے.جو طالب علم کامیابی کا خیال چھوڑ دیتا ہے اس کا حافظہ کند ہونا شروع کر دیتا ہے.روحانی حالتوں میں بھی یہی اصل کام کررہا ہے.جو قومیں گناہ کی معافی کی قائل نہیں وہ گناہ کے دور کرنے کے لئے پوری جدوجہد بھی نہیں کرتیں.جو فطرت کی پاکیزگی کی قائل نہیں وہ روحانی طاقتوں کو ان کے کمال تک پہنچانے کی طرف بھی متوجہ نہیں.رسول کریم ؐ نے مایوسی کی حالت کو دور کرنے کی طرف خاص توجہ فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مایوسی کی حالت کو دور کرنے کی طرف خاص توجہ فرمائی ہے.جیسے فرمایا کہ لِکُلِّ داءٍ دَوَاءٌ اِلَّا الْمَوْت.ہر مرض کی سوائے موت کے کہ اس کا آنا ضروری ہے دوا موجود ہے.یا فرمایا مَنْ قَالَ ھَلَکَ الْقَوْمُ فَھُوَ اَھْلَکَھُمْ جو کہے کہ قوم ہلاک ہو گئی ہے وہی قوم کا ہلاک کرنے والا ہے.کیونکہ وہ قوم کی امید کو توڑ کر اس کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے.پس چاہیے کہ انفرادی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی امید کی روح کو ترقی دی جائے.مگر یہ امر مدنظر رہے کہ امید ہو جس کے ساتھ قوتِ عملیہ ترقی کرتی ہے.نہ کہ امانی یا بیہودہ خواہشات ہوں جو سستی اور غفلت پیدا کرتی ہیں.جیسے مسلمانوں میں بجائے کوشش کرکے اپنی حالت درست کرنے کے خیال کے یہ خیال غالب رہا ہے کہ مسیح آکر سب دنیا کی نعمتیں ان کو دے دیں گے.محض خواہشات بھی مہلک ہوتی ہیں امانی یعنی محض خواہشات جب مستقل طور پر دل میں بیٹھ جائیں تو وہ بھی ناامیدی کی طرح مہلک ہوتی ہیں.
Page 509
فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا پس جب وہ (واپس ہو کر پھر) اس کے(یعنی یوسف کے) حضور حاضر ہوئے تو (اس سے) کہا (کہ) اے بادشاہ الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ ہمیں اور ہمارے (تمام) کنبہ کو( سخت) تنگی پہنچی (ہوئی) ہے اور ہم (بالکل) تھوڑی سی پونجی لائے ہیں پس آپ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا١ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ۰۰۸۹ (محض احسان کےطور پر) ہمیں (غلہ کا) پیمانہ پورا دے دیں اور ہمیں صدقہ (کے طور پر حق سے بھی کچھ زیادہ) دیں اللہ (تعالیٰ) صدقہ دینے والوں کو یقیناً (بڑا) اجر دیتاہے.حلّ لُغَات.اَلضُّرُّ.ضِدُّ النَّفْعِ.ضُرٌّ کے معنے ہیں نقصان.سُوْءُ الْحَالِ وَالشِدَّۃ.تنگ حالی وَفِی الْکُلّیَّاتِ اَلضَرُّ بِالْفَتْحِ شَائِعٌ فِیْ کُلِّ ضَرَرٍ وَبِالضَّمِّ خَاصٌ بِمَا فِی النَّفْسِ کَمَرَضٍ وَھُزَالٍ کلیات میں یوں لکھا ہے کہ ضُرٌّ کے معنے خاص اس تکلیف کے ہیں جو خود نفس میں ہو جیسے بیماری یا لاغر پن وغیرہ لیکن ضَرٌّ کا لفظ عام ہے اور ہر تکلیف پر بولا جاتا ہے.(اقرب) مُزْجٰۃٍ اَلْمُزْجٰی.اَلشَّیْءُ الْقَلِیْلُ مُزْجٰی کے معنے ہیں تھوڑی سی چیز.بِضَاعَۃٌ مُزْجَاۃٌ.اَیْ قَلِیْلَۃٌ.بِضَاعَۃٌ مُزْجَاۃٌ کے معنی ہیں تھوڑی سی پونجی.وَقِیْلَ رَدِیَّۃٌ لَمْ یَتِمَّ صَلَاحُھَا فَتُرَدَّ وَتُدْفَعُ رَغْبَۃً عَنْہَا.ایسی پونجی جس میں نقص ہو اور لوگ اس کو اچھا نہ سمجھ کر واپس کر دیویں.پس جِئْنَا بِبِضَاعَۃٍ مُزْجَاۃٍ کے معنی یہ ہوئے کہ ہم تیرے پاس حقیر اور تھوڑی چیز لائے ہیں.(اقرب) تفسیر.عزیز کا لفظ صرف سردار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے عَزِیْزٌ عربی لفظ ہے اور اس کے معنی معزز یا کامیاب کے ہوتے ہیں.یہ کوئی خاص عہدہ نہیں معلوم ہوتا.گو اب بعدکے زمانہ میں بادشاہ کے لئے بھی عزیز مصر کا لفظ استعمال ہونے لگا ہے لیکن مصریوں کی زبان عربی نہ تھی کہ ہم یہ خیال کریں ان کے وزراء عزیز کہلاتے تھے.پس میرے نزدیک یہ صرف سردار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے.اس صورت میں اس سے پہلے جو اِمْرَأَۃُ الْعَزِیْزِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنے بھی یہی ہیں کہ اس سردار یا اس عہدیدار کی عورت.برادان یوسف کا سہ بارہ مصر میں آنا یوسفؑ کے بھائیوں کا رویہ اس موقع پر ناقابل فہم ہے.یا تو وہ گناہ کی
Page 510
وجہ سے اخلاق میں گرتے چلے جاتے ہیں کہ آئے تو بھائیوں کی تلاش میں تھے.لیکن کیا صرف یہ کہ غلہ کا سوال کرنا شروع کر دیا.یا یہ ہے کہ اس خوف سے کہ ہمیں کوئی سازشی نہ سمجھے سوال صرف پردہ کے طور پر کیا.اور اس طرح اپنے واپس آنے کی غرض کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا.قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ اس نے کہا( کہ) کیا تمہیں (اپنا وہ سلوک) معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھاجبکہ تم جٰهِلُوْنَ۰۰۹۰ (اپنے فعل کی برائی سے )ناواقف تھے.تفسیر.معلوم ہوتا ہے اس موقع پر حضرت یوسفؑ کو غیرت آگئی اور وہ ڈرے کہ بھائی اپنے آپ کو اور ذلیل نہ کریں اور اپنے ظاہر کرنے کا ارادہ کرلیا.روحانی آدمی اور دنیادار میںفرق روحانی آدمی اور دنیادار میں کس قدر فرق ہوتا ہے.یوسفؑ کے بھائیوں نے یوسفؑ پر جسمانی طور پر ہی ظلم نہیں کیا ان کی عزت کو بھی برباد کرنا چاہا اور چوری کا الزام لگایا.اس کے برخلاف حضرت یوسفؑ ان کی غلطی کا ذکر کرتے ہیں تو اسے اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ کہہ کر ہلکا کردیتے ہیں.حضرت یوسفؑ کے اخلاق کی ایک جھلک یعنی جو کچھ تم لوگوں نے یوسف سے کیا تھا ایک بچپن کا کھیل تھا ورنہ تم لوگ تو بہت اچھے ہو.اخلاق کی ایسی ہی نمائشیں ہیں جو انسانیت کے حسن کو ظاہر کرتی ہیں اور جن کی نقل کرنے کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے.قَالُوْۤا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ١ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَ هٰذَاۤ اَخِيْ١ٞ انہوں نے کہا( کہ) کیا واقع میں آپ( ہی تو) یوسف( نہیں) ہیں.اس نے کہا( کہ) میں یوسف ہوں اور یہ میرا قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا١ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا بھائی ہے اللہ( تعالیٰ) نے ہم پر فضل کر دیا ہے.بات یقیناً یہی (درست) ہے کہ جو (شخص) تقویٰ اختیار کرے اور
Page 511
يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ۰۰۹۱ صبر کرے تو (ضرور اس کااجر پاتا ہے کیونکہ) اللہ( تعالیٰ) نیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہرگزنہیں کرتا.تفسیر.حضرت یوسف علیہ السلام نے جس اعلیٰ رنگ میں گزشتہ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے اس سے اور حضرت یعقوبؑ کے زور دینے پر کہ یوسف زندہ ہے اس کی تلاش کرو اور مصر میں تلاش کرو ان کے ذہن فوراً اس طرف منتقل ہو گئے کہ کہیں یہی تو یوسف نہیں.حضرت یوسفؑ کے اخلاق کا نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا پھر نمونہ دیکھو کہ انہیں ایک منٹ کے لئے شک میں نہیں رکھا اور فوراً اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور کس محبت سے تقویٰ اور صبر کی بھائیوں کو نصیحت بھی کی اور بتایا کہ سوال کرنے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے انسان مشکلات پر غالب نہیں آتا.بلکہ اصل گر تقویٰ اللہ اور صبر ہے.یعنی خدا پر توکل رکھے اور عمل کو جاری رکھے.مصائب سے گھبرائے نہیں.حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے سامنے بن یامین کو بھی بلا لیا تھا الفاظ قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے بن یامین کو بھی بلالیا تھا تبھی فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے.قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ اِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ۰۰۹۲ انہوں نے کہا اللہ کی قسم! اللہ نے آپ کو ہم پر ضرور فضیلت دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے.حل لغات.اٰثَرَہٗ اِیْثَارًا اِخْتَارَہُ وَاَکْرَمَہٗ.اٰثَرَہٗ.کے معنے ہیں ا سکو چن لیا اور اعزاز دیا.فَضَّلَہٗ اس کو بزرگی اور فضیلت دی اور قَدْاٰثَرَکَ اللہُ کے معنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی ہے.(اقرب) تفسیر.اب یوسفؑ کے بھائیوں کی نیک فطرت نے بھی سر اٹھایا اور انہوں نے یوسف کی خواب کی صحت کو تسلیم کرلیا اور کہا کہ تیرا خواب آخر پورا ہو کر رہا اور باوجود ہماری مخالفت کے جس غلطی کا اب ہم اقرار کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے تجھ کو فضیلت دی.
Page 512
قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ١ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ١ٞ وَ هُوَ اس نے کہا اب تمہیں( قطعاً )کوئی ملامت نہ ہوگی (اور) اللہ (بھی) تمہیں بخش دے گا اور وہ سب رحم کرنے والوں اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ۰۰۹۳ سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.اَلتَّثْرِیْبُ.اَلتَّقْرِیْعُ.تَثْرِیبٌ کے معنے ہیں ڈانٹ ڈپٹ.وَالتَّقْھِیْرُ بِالذَّنْبِ.قصور پر سرزنش.(مفردات) ثَرَبَہٗ لَامَہٗ وَعَیَّرَہُ بِذَنْبِہٖ.ثَرَبَہٗ کے معنے ہیں غلطی پر ملامت کی اور قصور پر برا بھلا کہا.اَلْمَرِیْضَ نَزَعَ عَنْہُ ثَوبَہٗ جب ثرب کا مفعول مریض ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس سے کپڑا اتارا.وَفِی الْمِصْبَاحِ ثَرَبَ عَلَیْہِ.عَتَبَ وَلَامَ.مصباح میں ثَرَبَ عَلَیْہِ کے یہ معنے لکھے ہیں کہ قصور پر ملامت و سرزنش کی.وَثَرَّبَہٗ وَثَرَّبَ عَلَیْہِ.قَبَّحَ عَلَیْہِ فِعْلَہٗ یُقَالُ لَاتَثْرِیْبَ عَلَیْکُمْ:- ثَرَّبَہٗ اور ثَرَّبَ عَلَیْہِ کے معنے ہیں کسی کے فعل کی برائی کا اظہار کیا.پس لَا تَثْرِيْبَ کے معنے ہوئے کہ تمہاری برائی کو کبھی ظاہر نہ کیا جائے گا.اور اس پر ملامت نہ کی جائے گی.(اقرب) تفسیر.حضرت یوسف ؑ کا اپنے بھائیوں کو معاف کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھایا.ا ور فوراً ان کی معافی کا اعلان کردیا.ورنہ اس وقت جبکہ ان کے بھائی غیرملک میں تھے اور بالکل بے یارومددگار تھے نہ معلوم کیا کیا خیال آرہے ہوں گے کہ اب یوسف کس کس طرح ہم سے بدلہ لے گا؟ پس حضرت یوسفؑ نے فوراً ہی اعلانِ عفو کرکے ان کے دلوں کو وساوس کی تکلیف سے بچا لیاجو اصل عذاب کی تکلیف سے کم نہیں ہوتی اور نہ صرف خود ہی معاف کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی مغفرت کی دعا کی اور اپنے بھائیوں کو اس مغفرت کی امید دلائی.یوسف علیہ السلام کا یہ کام اس قدر عظیم الشان ہے کہ صرف اس ایک کام کی وجہ سے وہ زندہ جاوید کہلانے کے مستحق ہیں.قرآن کریم اور بائبل دونوں میں اس واقعہ کو لیا گیا ہے.قرآن مجید نے حضرت یوسفؑ کے واقعہ کو ان کی اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے بیان کیا ہے لیکن دونوں کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ایک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو صرف اس امر کے اظہا رکے لئے
Page 513
قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ١ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ١ٞ وَ هُوَ اس نے کہا اب تمہیں( قطعاً )کوئی ملامت نہ ہوگی (اور) اللہ (بھی) تمہیں بخش دے گا اور وہ سب رحم کرنے والوں اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ۰۰۹۳ سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے.حلّ لُغَات.اَلتَّثْرِیْبُ.اَلتَّقْرِیْعُ.تَثْرِیبٌ کے معنے ہیں ڈانٹ ڈپٹ.وَالتَّقْھِیْرُ بِالذَّنْبِ.قصور پر سرزنش.(مفردات) ثَرَبَہٗ لَامَہٗ وَعَیَّرَہُ بِذَنْبِہٖ.ثَرَبَہٗ کے معنے ہیں غلطی پر ملامت کی اور قصور پر برا بھلا کہا.اَلْمَرِیْضَ نَزَعَ عَنْہُ ثَوبَہٗ جب ثرب کا مفعول مریض ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس سے کپڑا اتارا.وَفِی الْمِصْبَاحِ ثَرَبَ عَلَیْہِ.عَتَبَ وَلَامَ.مصباح میں ثَرَبَ عَلَیْہِ کے یہ معنے لکھے ہیں کہ قصور پر ملامت و سرزنش کی.وَثَرَّبَہٗ وَثَرَّبَ عَلَیْہِ.قَبَّحَ عَلَیْہِ فِعْلَہٗ یُقَالُ لَاتَثْرِیْبَ عَلَیْکُمْ:- ثَرَّبَہٗ اور ثَرَّبَ عَلَیْہِ کے معنے ہیں کسی کے فعل کی برائی کا اظہار کیا.پس لَا تَثْرِيْبَ کے معنے ہوئے کہ تمہاری برائی کو کبھی ظاہر نہ کیا جائے گا.اور اس پر ملامت نہ کی جائے گی.(اقرب) تفسیر.حضرت یوسف ؑ کا اپنے بھائیوں کو معاف کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھایا.ا ور فوراً ان کی معافی کا اعلان کردیا.ورنہ اس وقت جبکہ ان کے بھائی غیرملک میں تھے اور بالکل بے یارومددگار تھے نہ معلوم کیا کیا خیال آرہے ہوں گے کہ اب یوسف کس کس طرح ہم سے بدلہ لے گا؟ پس حضرت یوسفؑ نے فوراً ہی اعلانِ عفو کرکے ان کے دلوں کو وساوس کی تکلیف سے بچا لیاجو اصل عذاب کی تکلیف سے کم نہیں ہوتی اور نہ صرف خود ہی معاف کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی مغفرت کی دعا کی اور اپنے بھائیوں کو اس مغفرت کی امید دلائی.یوسف علیہ السلام کا یہ کام اس قدر عظیم الشان ہے کہ صرف اس ایک کام کی وجہ سے وہ زندہ جاوید کہلانے کے مستحق ہیں.قرآن کریم اور بائبل دونوں میں اس واقعہ کو لیا گیا ہے.قرآن مجید نے حضرت یوسفؑ کے واقعہ کو ان کی اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے بیان کیا ہے لیکن دونوں کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ایک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو صرف اس امر کے اظہا رکے لئے
Page 514
میں پڑھتے تھے یا دونوں رکعتوں میں تقسیم کرکے پڑھتے تھے.اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا١ۚ تم میرا یہ کرتہ لے جانا اور اسے میرے باپ کے سامنے(جا) رکھنا( اس سے) وہ (میرے متعلق) بصیرت پا کر وَ اْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَؒ۰۰۹۴ (میرے پاس )آئیں گے اور تم اپنا سارا کنبہ( بھی) میرے پاس لے آنا.حلّ لُغَات.بَصِیْرٌ.اَلْبَصِیْرُالْمُقْتَدِرُ عَلَی النَّظْرِ خِلَافُ الضَّرِیْرِ.بَصِیْرٌ کے معنے ہیں صحیح سالم نظر والا.رَجُلٌ بَصِیْرٌ بِکَذَا.عَالِمٌ بِہٖ خَبِیْرٌ: عالم واقف کار شخص (اقرب) تفسیر.لوگ کہتے ہیں کہ اس فقرہ سے ان کو ملامت کی ہے کہ جیسے تم نے پہلے قمیص ڈالی تھی ویسے ہی اب بھی قمیص لے جاؤ تاکہ شرمندہ ہوں.مگر میرے نزدیک یہ کمال عفو ہے کہ پہلے وہ قمیص لے جانے سے ہی ناراض ہوئے تھے اب بھی قمیص کے ذریعہ بشارت دو تاکہ وہ تم سے خوش ہوں.اور تمہارے گناہوں کی خدا تعالیٰ سے معافی مانگیں.لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ کہہ کر جب خود معاف کر دیا تو قمیص دے کر یہ خواہش ظاہر کی کہ باپ بھی ان کے لئے دعا کرے.يَاْتِ بَصِيْرًا کے معنے يَاْتِ بَصِيْرًا سے یہ مراد ہے کہ پہلے اس کو مومنانہ شان سے علم تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے مگر اب وہ بصیرت ظاہری پاکر میرے پاس آئے گا کہتے ہیں.رَجُلٌ بَصِیْرٌ بِکُنْھِہٖ اَیْ عَالِمٌ بِہٖ خَبِیرٌ.یعنی رَجُلٌ بصیرٌ کے معنے عالم اور واقف کار کے بھی ہوتے ہیں.مطلب آیت کا یہ ہے کہ پہلے الہام کے ماتحت جو حضرت یعقوبؑ کو ایمان تھا وہ اب امر واقع کے علم کی صورت میں بدل جائے.آخر میں بھائیوں کو عفو سے بڑھ کر حسنِ سلوک کی بشارت دی اور انہیں اپنے اہل ساتھ لاکر ان نعمتوں میں شریک ہونے کی دعوت دی.جو خدا تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں.
Page 515
وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ اور جب (ان کا) قافلہ (مصر سے) چل پڑا تو ان کے باپ نے (لوگوں سے) کہا (کہ) اگرایسا نہ ہو.کہ تم مجھے يُوْسُفَ لَوْ لَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ۰۰۹۵ جھٹلانے لگو تو(میں ضرورکہوں گا کہ) مجھے یقیناً یوسف کی خوشبو آرہی ہے.حلّ لُغَات.فَصَلَ فَصَلَ مِنَ الْبَلَدِ فُصُوْلًا: خَرَجَ مِنْہُ فَصَلَ مِنَ الْبَلَدِ کے معنے ہیں کہ شہر سے نکل پڑا.(اقرب) فَصْلٌ.اَلْفَصْلُ إِ بَانَۃُ اَحَدِ الشَّیْئَیْنِ مِنَ الْاٰخَرِ حَتّٰی یَکُوْنَ بَیْنَھُمَا فُرْجَۃٌ: فَصْلٌ کے معنے ہیں ایک چیز کو دوسری سے ایسے طور پر الگ کرنا کہ دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ ہوجائے.وَفَصَلَ الْقَوْمُ عَنْ مَکَانِ کَذَا وَانْفَصَلُوْا فَارَقُوْا.کسی جگہ سے علیحدہ ہوئے.(مفردات) اَلتَّفْنِیْدُ: نِسْبَۃُ الْاِنْسَانِ اِلَی الْفَنَدِ وَھُوَ ضَعْفُ الرَّأْیِ: تَفْنِیْدٌ کے معنے ہیں کسی کی طرف ضعف رائے منسوب کرنا.لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ:- قِیْلَ اَنْ تَلُوْمُوْنِیْ.بعض نے لَوْلَا اَنْ تُفَنِّدُوْنِ کے معنے یہ کئے ہیں کہ اگر تم مجھے ملامت نہ کرو.(مفردات) فَنِدَالرَّجُلُ فَنَدًا: خَرَفَ وَاَنْکَرَ عَقْلُہٗ لِھَرَمٍ اَوْمَرَضٍ.فَنِدَالرَّجُلُ کے معنے ہیں کہ بیماری یا بڑھاپے سے عقل کمزور ہو گئی.فِی الْقَوْلِ وَالرَّأْیِ.اَخْطَأَ کسی بات یا رائے میں غلطی کرنا کَذَبَ.جھوٹ بولا.تُفَنِّدُوْنِ.فَنَّدَ ماضی سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور فَنَّدَ کے معنے ہیں کَذَّبَہٗ ا سکو جھٹلایا.جَھَّلَہٗ.اس کو نادان قرار دیا.عَـــجَّزَہٗ.عاجز قرار دیا.لَامَہٗ اس کو ملامت کی.خَطَّأَرَأْیَہٗ وَضَعَّفَہٗ رائے کو غلط اور کمزور قرار دیا.(اقرب) تفسیر.رِیْحَ یُوْسُفَ سے مراد ان کی خبر ہے جب کسی چیز کے قریب عرصہ میں ملنے کی امید ہو تو کہتے ہیں کہ مجھے اس کی خوشبو آرہی ہے.یہی مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی فرماتے ہیں:
Page 516
آرہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار (براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد ۲۱ صفحہ ۱۳۱) لَوْ لَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِسے یہ مراد نہیں کہ تم مجھے پاگل نہ کہو بلکہ یہ فقرہ زور دینے کے لئے ہے.یعنی اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو میں یہ کہتا ہوں کہ یوسف کی ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے.اور گو یہ امر تمہاری سمجھ سے بالا ہے لیکن ہے بالکل سچا اور درست.قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ۰۰۹۶ انہوں نے کہا تو یقیناً اپنی پرانی غلطی میں (پڑا ہو ا) ہے تفسیر.مُلْہِمْ اور غَیْر مُلْہِمْ میں فرق ملہم اور غیر ملہم میں کتنا فرق ہوتا ہے.ملہم خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان لاکر جس یقین کے مقام پر ہوتا ہے دوسروں کو وہ کب نصیب ہوسکتا ہے.باوجود حضرت یعقوبؑ کے بتادینے کے ان کے گھر کے لوگ پھر بھی اس خبر کی تصدیق کرنا ناممکن سمجھتے ہیں اور آپ کو غلطی پر قرار دیتے ہیں.ضَلَالٌ کے معنے غلطی پر قائم ہونے کے بھی ہیں ضَلَالٌ کے معنے غلطی پر ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور محبت سے کسی امر پر قائم ہونے کے بھی ہوتے ہیں.گو اس فقرہ کے کہنے والے دوسرے لوگ ہیں لیکن چونکہ پھر بھی وہ مومن تھے خواہ کس قدر کمزور کیوں نہ ہوں اس جگہ پر یہی معنے چسپاں ہوتے ہیںکہ آپ اپنی شدت محبت کی وجہ سے ایسا خیال کرتے ہیں کہ آپ کے الہام کے ظاہری معنے ہیں ورنہ یوسف کا ملنا اب کہاں ممکن ہے.فَلَمَّاۤ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا١ۚ پس جونہی کہ (یوسف کے مل جانے کی) بشارت دینے والا( شخص حضرت یعقوب ؑ کے پاس) آیا اس نے اس قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ١ۙۚ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا (کُرتے)کو اس کے سامنے رکھ دیا.جس پر وہ (اس معاملہ میں) صاحب بصیرت ہو گیا (اور ان سے) کہا کیا میں
Page 517
تَعْلَمُوْنَ۰۰۹۷ نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں یقیناً اللہ (تعالیٰ) کی طرف سے (علم پا کر وہ کچھ) جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.حلّ لُغَات.اِرْتَدَّ اِرْتَدَّ عَلٰی اَثَرِہٖ.رَجَعَ اِرْتَدَّ عَلٰی اَثَرِہٖ کے معنے ہیں اپنے نشان پر واپس لوٹا.الٰی حَالِہِ عَادَ.اپنی اصلی حالت پر آگیا وَفِی الْقُرْاٰنِ فَارْتَدَّ بَصِیْرًا اَیْ عَادَ بَصِیْرًا بَعْدَ الْعَمٰی اور قرآن مجید کی آیت فَارْتَدَّ بَصِيْرًا کے معنے ہیں ناواقفیت کے بعد پھر صاحب بصیرت اور صاحبِ علم ہو گیا.بَصِیْرًا.بَصُرَ بِہٖ وَبَصِرَ بَصَارَۃً وَبَصَرًا: عَلِمَ بِہٖ جب بَصُرَ کے ساتھ ب کا صلہ آئے یا اس کا مصدر بَصَارَۃٌ اور بَصَرَ ہو تو اس کے معنے ہوتے ہیں کسی چیز کے متعلق اس کو اچھی طرح علم اور واقفیت حاصل ہو گئی.بَصِیْرٌ:اَلْبَصِیْرُ رَجُلٌ بَصِیْرٌ بِکَذَا.عَالِمٌ بِہٖ خَبِیْرٌ.رَجُلٌ بَصِیْرٌ کے معنے ہوتے ہیں کہ خوب واقف کار عالم آدمی (اقرب) پس اِرْتَدَّ بَصِیْرًا کے معنے ہوں گے کہ حضرت یعقوبؑ حضرت یوسفؑ کے معاملہ میں اچھی طرح صاحب بصیرت ہو گئے.تفسیر.اَلْقٰی عَلٰی وَجْہِہٖ کے معنے اَلْقٰی عَلٰی وَجْہِہٖ کے ظاہری معنے تو یہی ہیں کہ ان کے منہ پر ڈال دی لیکن قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ظاہر ہوا حضرت یوسفؑ کا معجزہ نہ تھا بلکہ حضرت یعقوبؑ کا.ورنہ قمیص سے آنکھیں اچھی ہونے پر انہیں چاہیے تھا کہ کہتے کہ دیکھو یوسفؑ نے کتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے کہ اس کی قمیص سے میری آنکھیں اچھی ہو گئی ہیں.مگر وہ قمیص ڈالنے کے نتیجہ میں کہتے یہ ہیں کہ دیکھو میری بات سچی ہو گئی کہ یوسفؑ زندہ ہے.قمیص کے سامنے آنے سے الہامی علم واقعاتی بن گیا پس اس سے ظاہر ہے کہ مطلب آیت کا یہی ہے کہ جب یوسفؑ کی قمیص حضرت یعقوبؑ کے سامنے رکھی گئی تو جو علم پہلے الہامی تھا اب وہ واقعاتی بن گیااور حضرت یعقوبؑ نے جیسا کہ انبیاء کی سنت ہے اپنی خوشی کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی شروع کردی کہ دیکھو جو خدا تعالیٰ نے کہا وہ سچ نکلا.اِرْتَدَّ بَصِیْرًا اندھے پن سے بینا ہونا مراد نہیں اِرْتَدَّ بَصِیْرًا سے یہ مراد نہیں کہ اندھے تھے پھر بینا ہوگئے بلکہ یہ کہ جس امر کو پہلے ایمان سے تسلیم کرتے تھے اب ظاہری علم کے ماتحت امرواقع کی طرح اس کو ماننے لگ گئے.
Page 518
انبیاء کا دو قسم کا علم روحانی اور ظاہری حواس سے الہام کی حقیقت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا علم دو قسم کا ہوتا ہے.ایک جو روحانی طور پر انہیں عطا ہوتا ہے اور دوسرا ظاہری حواس سے.جب کسی الہام کے ذریعہ سے کوئی خبر ملے تو ایمانی طور پر اس کا علم ہوتا ہے.لیکن وقوعہ کے طورپر نہیں پھر جب ظاہری حواس سے اس خبر کی تصدیق ہوجاتی ہے تو ایک دوسری قسم کا علم ان کو حاصل ہوتا ہے جس میں دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں.اسی دوسرے علم کے حصول کے اظہار کے لئےفَارْتَدَّ بَصِيْرًا کے الفاظ استعمال کئے ہیں.کیونکہ جب باطنی اور ظاہری حواس دونو ایک خبر کے مصدق ہوں تو علم کامل ہو جاتا ہے.جب تک ظاہری حواس سے وقوعہ کا علم نہ ہو یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ شاید آسمانی خبر تعبیر طلب ہو.یا اس کی کوئی اور توجیہہ ہو.لیکن جب ظاہر میں بھی خبر پوری ہو جاتی ہے تو انسان کو بصیرت کامل حاصل ہوجاتی ہے اور شبہ کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہتا.قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ۰۰۹۸ (تب) انہوں نے (یعنی حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے) کہا اے ہمارے باپ ! آپ ہمارے حق میں (خدا تعالیٰ سے) ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں ہم یقیناً خطا کار ہیں.تفسیر.جب تک انسان کا گناہ بخشا نہیں جاتا اس کے دل پر اس کا اثر رہتا ہے.چنانچہ یوسف کے بھائیوں سے اس وقت تک ایسی حرکات سرزد ہوتی رہی ہیں جو قلب کی صفائی کے نقص پر دلالت کرتی تھیں.لیکن جب حضرت یوسفؑ کی طرف سے لَاتَثْرِیْبَ عَلَیْکُمْ کہا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے عفو کے ساتھ اپنے عفو کو شامل کر دیا تو یوسفؑ کے بھائیوں کی بھی حالت بدل گئی اور انہوں نے اپنی توبہ کو کافی نہ سمجھ کر اپنے باپ سے بھی درخواست کی کہ تو ہمارے لئے خدا سے استغفار طلب کر.عام طور پر ایسے موقع پر لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں مگر اب وہ یہ نہیں کہتے کہ تو ہمیں معاف کر بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے لئے خدا سے مغفرت طلب کر.کیونکہ توبہ کے ساتھ ہی ان کے دل پر یہ روشن ہو گیا ہے کہ انسانی سزا یا ناراضگی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مقابل پر کوئی شے نہیں اس لئے سب سے پہلے انہیں خدا تعالیٰ سے صلح کرنی چاہیے اور اس کے نبی کے توسط سے اس کا عفو طلب کرنا چاہیے.اس درخواست میں حضرت یعقوبؑ کی معافی خود ہی آگئی کیونکہ خدا تعالیٰ سے ان کے لئے معافی وہ تب ہی طلب کرسکتے تھے جبکہ خود معاف کرچکے ہوں.
Page 519
قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ١ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ اس نے کہا میں (ضرور) تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا یقیناً وہی( ہے جو) بہت بخشنے والا الرَّحِيْمُ۰۰۹۹ (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.تفسیر.ایک نکتہ اس جگہ ایک عجیب نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے.حضرت یعقوبؑ نے سَوْفَ کا لفظ بولا ہے جو مستقبل بعید کے لئے اور کلام پر زور دینے کے لئے آتا ہے.اس میں انہوں نے گویا انسانی فطرت کا صحیح نقشہ کھینچا ہے.اور بتایا ہے کہ رنج اور غصہ زائل ہوکر فوراً نئی محبت پیدا نہیں ہوسکتی.انسان کے دل سے رنج و غصہ کے اثرات مٹنے کے لئے ایک زمانہ چاہیے.حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے معافی کے الفاظ میں فرق حضرت یوسفؑ تو چونکہ دیر سے تیار ہورہے تھے کہ معاف کر دیں اس لئے انہوں نے سَوْفَ نہیں کہا بلکہ فوراً لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ١ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ کہہ دیا.مگر حضرت یعقوبؑ کو اچانک یہ خبر ملی اس لئے انہوں نے کہا کہ کچھ وقت چاہیے تا قلب سے ناراضگی کا اثر دور ہوکر استغفار کی تحریک ہو.مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹوں کے اس ملال اور گھبراہٹ کو جو سَوْفَ کے لفظ کی وجہ سے پیدا ہوسکتا تھا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ کہہ کر دور کر دیا کہ گھبراؤ نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے زنگ دھودے گا اور بہت رحم کرے گا.ہمارے ملک میں بعض لوگ قصور کرکے اسی وقت اڑ بیٹھتے ہیں کہ آپ معاف کریں گے تو اٹھوں گا اور ان کی مراد اس معافی سے یہ ہوتی ہے کہ دل میں ان کے متعلق وہی محبت پیدا ہوجائے.حالانکہ یہ بات قدرتی قاعدہ کے خلاف ہے.معافی کی دوا قسام معافی دو قسم کی ہوتی ہے ایک یہ کہ سزا نہ دی جائے.یہ تو ایک منٹ میں ہوسکتی ہے.دوسرا یہ کہ پھر وہی تعلقات محبت ہوجائیں.سو اس کے لئے کچھ وقت ہوتا ہے اور یہ جبر یا ستیہ گرہ سے نہیں ہوسکتی.
Page 520
فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَ قَالَ ادْخُلُوْا پھر جب وہ (سب) یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور( سب سے) کہا (کہ) مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَؕ۰۰۱۰۰ اگر اللہ (تعالیٰ) کی مشیت (شامل حال) ہو تو تم امن (اور سلامتی) کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ.تفسیر.سوتیلی ماؤں کا ایسا ہی ادب چاہیے جیسے حقیقی ماؤں کا اللہ تعالیٰ نے بار بار اَبَوَیْہِ کا لفظ رکھ کر یہ بتایا ہے کہ باوجودیکہ حضرت یوسفؑ کی حقیقی والدہ فوت ہوچکی تھیں اور موجودہ والدہ ان کی سوتیلی والدہ تھیں مگر وہ ان کا پورا ادب اور لحاظ و احترام کرتے تھے (پیدائش باب ۳۵ آیت ۱۹).اس میں یہ نصیحت ہے کہ اولاد کو یہ مدنظر رکھنا چاہیے کہ سوتیلی مائیں بھی مائیں ہی ہوتی ہیں.ان کے ساتھ سلوک کرنے میں اور ان کے احترام میں اسلام کوئی فرق نہیں کرتا.پس اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کا بھی ویسا ہی لحاظ کریں جیسا کہ حقیقی ماؤں کا کرنا چاہیے.حضرت یوسفؑ نے اپنے والد کا استقبال کیا اُدْخُلُوْا مِصْرَ سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت یوسفؑ اپنے باپ کے استقبال کے لئے آگے آئے تھے.استقبال پسندیدہ امر ہے جس سے ثابت ہوا کہ ایک نبی بھی اپنے والدین کے استقبال کے لئے باہر جاتا ہے تو استقبال نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ امر ہے.حضرت یوسف ؑکی روحانیت حضرت یوسفؑ کی روحانیت دیکھو کہ ان کے بھائی تو بڑے بڑے کاموں کے لئے انشاء اللہ نہیں بولتے اور تمام کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں.مگر یہ ہیں کہ اس حالت میں بھی کہ شہر سامنے ہے سواریاں موجود ہیں اور خود گویا وزیراعظم ہیں مگر انشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود ان سامانوں کے ممکن ہے کہ اگر خدا نہ چاہے تو ہم داخل نہ ہوسکیں.انشاء اللہ کہنے سے روحانی ترقی سچے دل سے انشاء اللہ کہنا روحانی ترقی سے بہت کچھ تعلق رکھتا ہے.زندگی سے ماضی انسان کے بس سے نکل چکا ہوتا ہے.حال اتنا چھوٹا عرصہ ہے کہ درحقیقت وہ ماضی اور مستقبل کی سرحد کا نام ہے.باقی رہا مستقبل سو وہی اصل زمانہ ہے جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے.پس جب انسان مستقبل کے
Page 521
کاموں کے ساتھ انشاء اللہ کہتا ہے تو اپنے ارادہ اور فعل میں خدا تعالیٰ کو شامل کرلیتا ہے اور اس طرح انہیں شیطانی تصرف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ یقینی امر ہے کہ جو شخص سچے دل سے انشاء اللہ کہہ کر اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کو شامل کرلے گا جب اس کام کا وقت آئے گا تو وہ اسے نیکی اور تقویٰ کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرے گا.دوسرے جب کوئی شخص انشاء اللہ سوچ سمجھ کر کہنے اور پھر مستقبل کے کام کے متعلق کہنے کی عادت ڈال لے تو وہ گناہ کا ارادہ کرنے سے بچ جاتا ہے.کیونکہ گناہ کے متعلق انشاء اللہ نہیں کہا جاسکتا.پس جب کبھی کسی بد فعل کے متعلق وہ ارادہ ظاہر کرنے لگے گا انشاء اللہ کی عادت اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی پیدا کردے گی.ذکر الٰہی اور توکّل روحانیت کی جان ہیں علاوہ ازیں انشاء اللہ کہنے کی عادت ذکرالٰہی کا باعث ہوتی ہے اور توکل کا سبق دیتی ہے اور یہی باتیں روحانیت کی جان ہیں.حضرت یوسفؑ کو مصر میں آل یعقوب کے لئے پیش آمدہ خطرات کا علم دیا گیا تھا اُدْخُلُوْا اٰمِنِیْنَ کے الفاظ گو دعائیہ نہیں لیکن مراد اس سے دعا ہے.شاید حضرت یوسفؑ کو الہاماً ان خطرات کا علم دیا گیا ہو جو آئندہ آل یعقوب کو مصر میں پیش آنے والے تھے.پس انہوں نے ان کے لئے دعا کردی کہ ا للہ تعالیٰ ان خطرات کے تباہ کن اثرات سے ان کو محفوظ رکھے.آنحضرت صلعم کی حضرت یوسفؑ سے مشابہت اس معاملہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسفؑ سے مشابہت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہر میں داخل ہونے سے پہلے دعا کرلیا کرتے تھے.شہر میں داخل ہونے کی دعا آپؐ شہر میں داخلہ سے پہلے ان الفاظ میں دعا کرتے اللّٰھُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَااَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرَضِیْنَ السَّبْعِ وَمَااَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّیٰطِیْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّیَاحِ وَمَاذَرَیْنَ.فَاِنَّا نَسْئَلُکَ خَیْرَھٰذِہِ الْقَرْیَۃِ وَخَیْرَ اَھْلِہَا وَخَیْرَ مَافِیْہَا وَنَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ ھٰذِہِ الْقَرْیَۃِ وَشَرِّ اَھْلِہَا وَشَرِّ مَافِیْہَا اللّٰہُمَّ بَارِکْ لَنَا فِیْہَا وَارْزُقْنَا جَنَاھَا (یا جَیَاھَا) وَاَعِذْنَا مِنْ وَبَاھَا وَحَبِّبْنَا اِلٰی اَھْلِہَا وَحَبّبْ صَالِـحِیْ اَھْلِہَا اِلَینَا.شہر میں داخل ہونے کی دعا کے متعلق تجربہ میرا اور دوسرے دوستوں اور ہم سے پہلے بزرگوں کا بھی یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو آفات سے بچاتا ہے.
Page 522
وَ رَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا١ۚ وَ قَالَ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور وہ( سب) اس کی وجہ سے (خدا کا شکر کرتے ہوئے) سجدہ میں گر گئے يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ١ٞ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ اور اس نے (یعنی یوسف نے) کہا اے میرے باپ یہ میری پہلے سے (خواب میں) دیکھی ہوئی بات کی حقیقت کا حَقًّا١ؕ وَ قَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَ جَآءَ اظہارہے اللہ (تعالیٰ) نے اسے پورا کر دیا ہے اور اس نے مجھ پر (بہت بڑا) فضل کیا ہے.کیونکہ اس نے (پہلے) بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَ مجھے قید خانہ سے نکالا اور( مجھے اس عزت کے مقام پر پہنچا کر اس کے بعد )وہ تمہیں جنگل (کے علاقہ) سے (نکال کر بَيْنَ اِخْوَتِيْ١ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ١ؕ اِنَّهٗ هُوَ میرے پاس) لایا.بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا.میرا رب جس الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ۰۰۱۰۱ سے چاہتا ہے لطف (و احسان) کا معاملہ کر تا ہے یقیناً وہی( ہے جو) خوب جاننے والا (اور) حکمت والا ہے.حلّ لُغَات.رَفَعَ رَفَعَہٗ رَفْعًا ضِدُّ وَضَعَہٗ.رَفَعَ کے معنے ہیں بلند کرنا.زَیْدًا اِلَی الْحَاکِمِ رَفْعًا وَرُفْعَانًا قَدَّمَہٗ اِلَیْہِ لِیُحَاکِمَہُ زید کو حاکم کے سامنے مقدمہ کے فیصلہ کے لئے حاضر کیا.اِلَی السُّلْطَانِ رُفْعَانًا قَرَّبَہٗ.بادشاہ کے حضور پیش کیا.(اقرب) اَلرَّفْعُ یُقَالُ تَارَۃً فِی الْاَجْسَامِ الْمَوْضُوْعَۃِ اِذَا أَعْلَیْتَہَا عَنْ مَقَرِّھَا وَتَارَۃً فِی الْمَنْزِلَۃِ اِذَا شَرَّفْتَہَا.رَفَعٌ کا لفظ جب اجسام کے لئے استعمال ہو تو کبھی اس کے معنے ان کو ان کی اصل جگہ سے بلند کرنے کے ہوتے ہیں اور کبھی درجہ اور رتبہ میں فضیلت دینے کے.وَاِلَی السَّمَآءِ کَیْفَ رُفِعَتْ.اِشَارَۃٌ اِلَی الْمَعْنَیَیْن اِلٰی اِعْلَاءِ مَکَانِہٖ وَاِلَی مَاخُصَّ بِہٖ مِنَ الْفَضِیْلَۃِ وَشَرَفِ الْمَنْزِلَۃِ چنانچہ آیت اِلَی السَّمَآءِ کَیْفَ رُفِعَتْ میں رفع کے
Page 523
دونوں مذکورہ بالا معنے مراد ہیں.بلندی مکان اور فضیلت و شرف.(مفردات) اَلْعَرْشُ.اَلْعَرْشُ سَرِیْرُ الْمَلِکِ.اورنگ شاہی.(اقرب) اَلْعَرْشُ فِی الْاَصْلِ شَیْءٌ مُسَقَّفٌ.عرش کے اصلی معنی چھتی ہوئی چیز کے ہیں.وَمِنْہُ قِیْلَ عَرَشْتُ الْکَرْمَ وَعَرَّشْتُہٗ.اِذَا جَعَلْتُ لَہٗ کَھَیْئَۃِ سَقْفٍ.چنانچہ انہی معنوں میں عَرَّشْتُ الْکَرْمَ کا فقرہ استعمال ہوتا ہے کہ انگوروں کی بیل کے پھیلنے کے لئے چھت کی قسم کی کوئی چیز بنادی.وَسُمِّیَ مَجْلِسُ السُّلْطَانِ عَرْشًا اِعْتِبَارًا بِعَلُوِّہٖ.اور بادشاہ کی مجلس کو اس کی رفعت کی وجہ سے عرش کہہ دیتے ہیں.وَکُنِّیَ بِہٖ عَنِ الْعِزِّ وَالسُّلْطَانِ وَالْمَمْلَکَۃِ.نیز عرش سے مراد کنایۃً عزت و غلبہ اور بادشاہت بھی لی جاتی ہے.مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت۵پس رَفَعَ اَبَوَیْہِ عَلَی الْعَرْشِ کے معنے ہوئے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا یا بادشاہ کے حضور پیش کیا.(مفردات) خَرَّخَرُّوْا.خَرَّ ماضی سے جمع غائب کا صیغہ ہے.جس کے معنے ہیں سَقَطَ.سُقُوْطًا یُسْمَعُ مِنْہُ خَرِیْرٌ.ایسے طور پر گرنا کہ اس سے آواز سنائی دے.وَالْخَرِیْرُ یُقَالُ لِصَوْتِ الْمَاءِ وَالرِّیْحِ وَغَیْرِ ذٰلِکَ مِمَّا یَسْقُطُ مِنْ عُلُوٍّ.اور خریر اس آواز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے اوپر سے گرنے یا ہوا اور پانی کے چلنے سے پیدا ہو.وقَوْلُہٗ خَرُّوْالَہٗ سُجَّدًا فَاسْتِعْمَالُ الْخَرِّ تَنْبِیْہٌ عَلٰی اِجْتِمَاعِ اَمْرَیْنِ.السُّقُوْطِ.وَحُصُوْلِ الصَّوْتِ مِنْہُمْ بِالتَّسْبِیْحِ.اور خَرُّوْا لَہٗ سُجَّدًا کے الفاظ سے دو باتوں کی طرف اشارہ ہے.(۱) گرنا (۲) تسبیح کرنے کی وجہ سے آواز کا پیدا ہونا.(مفردات) نَزَغَہٗ.طَعَنَ فِیْہِ.نَزَغَ کے معنے ہیں طعنہ زنی کی.اِغْتَابَہٗ کسی کی غیبت کی.وَذَکَرَہٗ بِقَبِیْحٍ.اور اس کے متعلق بدگوئی کی.اور نَزَغَ بَیْنَ الْقَوْمِ کے معنی ہیں اَغْرٰی وَاَفْسَدَ وَحَمَلَ بَعْضَہُمْ عَلٰی بَعْضٍ.کہ قوم کے درمیان بگاڑ و فساد ڈالا اور ایک کو دوسرے کے خلاف برانگیختہ کیا.اور نَزَغَ الشَّیْطٰنُ بَیْنَہُمْ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کے درمیان بگاڑ ڈال دیا.(اقرب) شَیْطٰنٌ کا لفظ دو مختلف مادوں سے بن سکتا ہے.(۱) شَطَنَ.(۲) شَاطَ یا تو یہ شَطَنَ سے فَیْعَالٌ کے وزن پر ہے اور شَطَنَ عَنْہُ کے معنے ہیں اَبْعَدَ دور ہو گیا.اور شَطَنَ الدَّارُ کے معنے ہیں گھر دور ہو گیا.پس اس مادہ کے لحاظ سے اس کے معنے ہوں گے کہ وہ ہستی جو حق سے خود بھی دور ہے اور دوسروں کو بھی دور کرنے والی ہے اور اگر شَاطَ اس کا مادہ مانا جائے تو اس کے معنے ہوں گے کہ وہ ہستی جو حسد اور تعصب کی وجہ سے جل جائے یا ہلاک ہو
Page 524
جائے.کیونکہ شَاطَ الشَّیْءُ کے معنے ہیں اِحْتَرَقَ جل گئی اور شَاطَ فُلَانٌ کے معنی ہیں ھَلَکَ ہلاک ہو گیا.شَیْطٰنٌ اس سے فَعْلَانٌ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے.ان معنوں کے علاوہ شَیْطٰنٌ کے معنے لغت میں مندرجہ ذیل لکھے ہیں.رُوْحٌ شَرِیْرٌ.بدروح.کُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّدٍ.سرکش اور حد سے بڑھنے والا.اَلْحَیَّۃُ سانپ.(اقرب) لَطِیْفٌ.لَطَفَ میں سے بنا ہے جس کے معنے ہیں لَطَفَ بِہٖ وَلَہٗ لُطْفًا.رَفَقَ بِہٖ.نرمی کی.لَطَفَ اللہُ لِلْعَبْدِ وَبِالْعَبْدِ.رَفَقَ بِہٖ.اللہ نے بندے پر شفقت کی.وَاَوْصَلَ اِلَیْہِ مَایُحِبُّ بِرِفْقٍ.اور اس کی مراد اچھی طرح پوری کردی.وَفَّقَہٗ.نیک کام کی توفیق دی.عَصَمَہٗ.اس کو شر سے محفوظ رکھا.لَطُفَ الشَّیْءُ لَطَافَۃً.صَغُرَ وَدَقَّ.لَطُفَ الشَّیْءُکے معنے ہیں کہ کوئی چیز چھوٹی اور باریک ہو گئی.مِنَ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی مَعْنَاہُ الْبَرُّ بِعِبَادِہٖ الْمُحْسِنُ اِلٰی خَلْقِہٖ بِاِیْصَالِ الْمَنَافِعِ اِلَیْہِمْ بِرِفْقٍ وَلُطْفٍ اَوِالْعَالِمُ بِخَفَا یَاالْامُوْرِ وَدَقَائِقِہَا.اور جب لطیف کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ بندوں پر اور مخلوق پر احسان اور شفقت و مہربانی کرنے والا.اور محبت و احسان کے ساتھ ان کو نفع پہنچانے والا.مخفی باتوں کو جاننے والا.(اقرب) تفسیر.رَفَعَ کے معنے اعلیٰ پایہ کے انسان کے سامنے پیش کرنے کے بھی ہوتے ہیں.کہتے ہیں رَفَعَ اِلَی السُّلْطَانِ اَیْ قَرَّبَہٗ.بادشاہ کے حضور پیش کیا.رفَعَ اَبَوَیْہِ عَلَی الْعَرْشِ کے دو معنے پس اس آیت کے دو معنے ہوسکتے ہیں.اول یہ کہ انہوں نے اپنے والدین کو بادشاہ کے پیش کیا.بائبل سے انہی معنوں کی تصدیق ہوتی ہے.کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا.دوسرے یہ معنے ہوسکتے ہیں کہ ان کو اپنے تخت پر بٹھایا.پرانے زمانہ میں رواج تھا کہ نائب سلطنت کے لئے بھی ایک تخت ہوا کرتا تھا.پس ممکن ہے کہ حضرت یوسفؑ کے لئے بھی ایک تخت مقرر ہو اور حضرت یوسفؑ نے بادشاہ کی اجازت سے ان کو اپنے تخت پر بٹھایا ہو.وَخَرُّوْالَہُ سُجَّدًا.خَرَّالْمَاءُ یَخِرُّ خَرِیْرًا.صَاتَ پانی نے بہتے ہوئے آواز پیدا کی.وَکَذٰلِکَ الرِّیْحُ وَالْقَصَبُ اسی طرح ہوا کے چلنے اور سرکنڈوں کے ہلنے سے جب آواز پیدا ہو تو خَرّ کا لفظ استعمال کرتے ہیں.اَلْعُقَابُ.صَاتَ خُفُوْقُ جَنَاحَیْہَا.عِقَابٌ کے لئے جب خر کا لفظ بولا جائے تو یہ مراد ہوگی کہ اس کے بازوؤں کے ہلنے سے آواز پیدا ہوئی.اَلنَّائِمُ غَطَّ سونے والے نے اونچی آواز سے خرانٹے لئے.خَرَّسَاجِدًا.اِنْکَبَّ عَلَی الْاَرْضِ.سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر گیا.وَالْحَجَرُ.صَوَّتَ مُنْحَدِرًا.پتھر کے گرنے سے آواز پیدا ہوئی.(اقرب الموارد)
Page 525
خَرُّوْا لَہٗ سُجَّدًا کے دو معنے خرّ کے جتنے معنے بیان ہوئے ہیں ان سب میں آواز کے معنے پائے جاتے ہیں.اسی بنا پر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خَرَّ سَاجِدًا یہ اس وقت بولیں گے جبکہ کوئی شخص بے تحاشا سبحان اللہ کہتا ہوا گر پڑے.اگر آواز ساتھ نہ ہو تو خالی سَجَدَ بولا جائے گا.تو خَرُّوْا لَہٗ سُجَّدًا کے معنے یہ ہوئے کہ وہ بے تحاشا سبحان اللہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے یا انہوں نے بڑے جوش و خروش سے سجدہ کیا اور ان کے اس طرح سجدہ میں گرنے سے ایک آواز بھی پیدا ہوئی.حضرت یوسف سجدہ کے باعث تھے نہ کہ مسجود یہ مراد نہیں کہ انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا بلکہ یہ مراد ہے کہ یوسفؑ کی ترقی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئے.پس یوسف علیہ السلام سجدہ کے باعث تھے نہ کہ مسجود.نبیوں کے آداب وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ.اس آیت سے نبیوں کے اعلیٰ آداب کا پتہ چلتا ہے.حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لوگ قحط اور تنگی سے بچ کر عزت اور آرام کے مقام پر چلے آئے تھے مگر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے.آپ لوگوں کو یہاں لے آیا ہے.مومن کو کلام کرتے ہوئے ہمیشہ اس اصل کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی دل شکنی نہ ہو بلکہ اس کا ادب اور احترام کلام سے ظاہر ہو.یہ نہ صرف تمدن کی ترقی کا موجب ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی موجب ہوتا ہے.بعض لوگ کلام میں بے احتیاطی کرتے ہیں اور اس کا نام سادگی رکھتے ہیں حالانکہ نبیوں کا یہ طریق نہیں وہ ہمیشہ کلام میں دوسرے کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں اور یہی طریق مومنوں کو اختیار کرنا چاہیے.رسول کریم ؐہر ایک کی بات متوجہ ہو کر سنتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آتا ہے ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی سے کلام کرتے تو اس کی طرف متوجہ ہوکر کلام کرتے اور اگر کوئی آپؐ سے کلام کرتا تو اس کی طرف متوجہ ہوکر سنتے(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام زیر عنوان امر عدی بن حاتم ).آج کل بڑے لوگوں میں یہ عادت ہوگئی ہے کہ جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو اس کی طرف آدھا رخ رکھتے ہیں اور جب کوئی ان سے کلام کرے تو اس کی طرف پورے متوجہ نہیں ہوتے.پوری توجہ سے کسی کی بات نہ سننا کبر پیدا کرتی ہے یہ سب غیرمومنانہ افعال ہیں ان سے مومن کو کلی اجتناب چاہیے ورنہ دل پر زنگ لگ کر کبر پیدا ہو جاتا ہے.شیطان کا مفہوم ہر بری تحریک جس کا منبع معلوم نہ ہو قرآن اسے شیطان کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ وہ باریک خیالات کا نتیجہ ہوتی ہے اور شیطان کا لفظ اپنے مادہ شطن کے لحاظ سے ایک ایسی ہستی پر دلالت کرتا ہے جو دور
Page 526
سے وساوس پیدا کرتی ہے اور کبھی یہ لفظ اس بدروح کے لئے استعمال ہوتا ہے جو فرشتوں کے مقابلہ پر بدی کے اسباب کی محرک ہوتی ہے اور کبھی ان پوشیدہ تحریکات پر جو گزشتہ اعمال کے نتیجہ میں دل میں پیدا ہوکر انسان کو ایسے موقع پر گناہ کی طرف لے جاتی ہے جبکہ بظاہر اس کے بدی میں مبتلا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی.صفت لَطِیْفٌ کی تشریح اللہ تعالیٰ کے لئے جب لَطِیْفٌ کا لفظ آوے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ مخفی باتوں کو جاننے والا.لوگوں کی خبرگیری کرنے والاا ور محبت اور احسان کے ساتھ ان کو نفع پہنچانے والا ہے.گویا وہ خبرگیری کرتا ہے اور اس کی خبرگیری کا منبع محبت ہوتی ہے.وہ خبرگیری کرنے کے ذرائع پیدا کرتا ہے اور اس کا محرک بھی محبت ہی ہوتی ہے اور احسان کرتا ہے تو وہ بھی رفق اور لطف کے ساتھ کرتا ہے.یعنی باوجودیکہ وہ غنی ہے مگر اپنے استغناء کو بندے سے چھپاتا ہے تا بندے کی محبت خدا کے ساتھ بڑھے.گویا اس کے تمام افعال میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے.لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ کہہ کر بتایا کہ وہ اپنی مشیت کے مطابق لطف کرتا ہے اور یہ بھی کہ اس کا لطف ہر ایک کی استعداد کے مطابق اس پر نازل ہوتا ہے.اَلْحَكِيْمُ کہنے کی وجہ اَلْحَكِيْمُکہہ کر اللہ تعالیٰ سے الزام دور کیا کہ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خواب تو ترقی کی دکھائی تھی مگر ہوا یہ کہ ایک لمبا عرصہ تک سخت مصائب میں سے گزرنا پڑا.لیکن اگر غور کریں تو یہی تکالیف اگر ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی کا موجب ہوئیں تو دوسری طرف ان کے بھائیوں کی پاکیزگی اور توبہ کا موجب ہوئیں.پس خدا تعالیٰ کا یہ فعل حکمت سے خالی نہ تھا.ان تکالیف کے بغیر اگر حضرت یوسفؑ کو عزت ملتی تو وہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کی عظمت کو اس قدر ثابت نہ کرتی اور نہ یوسف کے بھائیوں کے دلوں کی صفائی ہوتی.پس جو کچھ ہوا حکمت کے ماتحت ہوا نہ کہ بے سبب.رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ اے میرے رب! تو نے مجھے حکومت کا ایک حصہ (بھی) عطا کیا ہے اور اپنی باتوں کی حقیقت کا بھی کچھ علم تو نے الْاَحَادِيْثِ١ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١۫ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي مجھے بخشا ہے (اے) آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے تو( ہی) دنیا اور آخرت (دونوں)میں میرا مدد گار ہے
Page 527
الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ١ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ۰۰۱۰۲ (جب بھی میری موت کا وقت آئے) مجھے اپنی کامل فرمانبرداری کی حالت میں وفات دے اور صالحین (کی جماعت) کےساتھ ملا دے.حلّ لُغَات.فَاطِرٌ.فَاطِرٌ: فَطَرَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کے معنے ہیں پیدا کرنے والا.مزید تشریح کے لئے دیکھو ہودآیت۵۱.تَوَفَّنِیْ مجھ کو وفات دے.مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس آیت۱۰۱.تَأْوِیْلٌ تاویل حقیقت.مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف آیت۲۲.تفسیر.برگزیدہ لوگوں کا خدا تعالیٰ سے عشق یہ آیت اس عشق پر دلالت کرتی ہے جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں کے دلوں میں موجزن ہوتا ہے.ان کے رشتہ داروں کی ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے کرتے یکدم اللہ تعالیٰ کی محبت کا شعلہ اٹھتا ہے اور وہ سب کچھ بھول بھال کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں.دنیاومافیہا ان کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں رَبِّ قَدْ اٰتَیْتَنِیْ مِنَ الْمُلْکِ اے خدا! یہ سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے.یہی وہ حقیقی سجدہ ہے جو انسان کو روحانی میدان میں ترقی بخشتا ہے.ظاہری سجدہ تو ایک وقتی سجدہ ہے.اصل سجدہ یہی ہے کہ خوشی اور غم کے موقعہ پر انسان کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ جائے اور اس کا دل بے تاب ہوکر اس کی طرف جھک جائے.اس مقام کے حصول کے بغیر کوئی روحانی ترقی حاصل نہیں ہوسکتی اور اس جنت میں انسان داخل نہیں ہوسکتا جس کے بغیر اگلے جہان کی جنت کا ملنا ناممکن ہے.ویری کا اعتراض اور اس کا جواب ویری نے اس جگہ اعتراض کیا ہے کہ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ میں وہی قرآن والا کبر ہے.میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن والا کبر نہیں بلکہ قرآن والی محبت ہے کہ ہر بات میں خدا کا ذکر کردیتے ہیں.بائبل والی خودغرضی نہیں کہ کام ہو گیا تو نام لینا ہی چھوڑ دیا.مُلک سے مراد تصرف ہے نہ کہ بادشاہت رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت مل گئی تھی.مگر اس سے یہ مراد نہیں.ملک سے مراد تصرف اور قبضہ ہے اور وہ ان کو بادشاہِ وقت کے حکم سے حاصل تھا.وَ عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ تو نے مجھے خوابوں کی حقیقت سکھا دی یعنی انہیں پورا کرکے دکھا دیا.یا یہ کہ تو نے مجھے تعبیر الرؤیا کا علم سکھا دیا.انبیاء کا وجود صفاتِ الٰہیہ کا ثبوت ہوتا ہے فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.انبیاء کا وجود صفات الٰہیہ کا ثبوت ہوتا
Page 528
ہے.حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہونے کا ثبوت ہے.جب میں لاشئی محض تھا خدا تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ ترقیات کی خبر دی اور پھر میں جو ایک معمولی حیثیت کا انسان تھا مجھے طاقت دے کر ایک بڑی حکومت بخشی اور گویا ایک نیا آسمان اورزمین پیدا کر دیا.پس میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کے فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہونے کا ثبوت مل گیا ہے.اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ.درحقیقت دعا ہے یعنی اے خدا تو میرا دنیا و آخرت میں مددگار بن.چنانچہ اسی کی تشریح میں فرمایاتَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ.یعنی اس دنیا میں میرا انجام بخیر ہو اور اگلے جہان میں میں ان لوگوں میں شامل رہوں جو ترقی کے قابل ہیں.ولایت دُنیوی اور ولایت اُخروی کی تفسیر ولایت دنیوی کی تفسیر تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا کے الفاظ سے کی ہے اور ولایت اخروی کی تفسیر اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ کے الفاظ سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا کہہ دیا تو اَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ کی کیا ضرورت تھی؟ جو مسلم فوت ہوگا صالحین میں اٹھے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم کا لفظ عام ہے.ایک شخص جس کا اسلام حقیقت میں کمزور ہے وہ ظاہری شریعت کی رو سے مسلم کہلا سکتا ہے اور ایسا شخص تھوڑی سی سزا پاکر جنت میں داخل ہو جائے گا مگر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے وہ ایسا مسلم ہونے کی حالت میں جائیں کہ آگے جاکر صالحین کے ساتھ الحاق ہو یعنی ایسے کامل مسلم ہوں کہ بغیر کسی روک کے مرنے کے بعد ترقیات ہی کی طرف قدم اٹھے اور یہی وہ مقام ہے جس کی جستجو مومن کو ہونی چاہیے.ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ١ۚ وَ مَا كُنْتَ (اے ہمارے رسول!) یہ (بیان) غیب کی خبروں میں سے ہے ہم اسے تجھ پر وحی (کےذریعے سے ظاہر) کرتے لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُوْنَ۰۰۱۰۳ ہیں اور جب انہوں نے (یعنی تیرے دشمنوں نے) اپنی بات پر اس حال میں اتفاق کر لیا کہ وہ( سب کے سب) تیرے خلاف کوششیں کر رہے تھے تو تُو (اس وقت) ان کے پاس (موجود) نہیں تھا.حلّ لُغَات.اَجْمَعُوْا.اَجْمَعَ ماضی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے.اور اَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَی الْاَمْرِ کے معنے ہیں اِتَّفَقُوْا عَلَیْہِ.قوم نے کسی بات پر اتفاق کرلیا.(اقرب)
Page 529
تفسیر.حضرت یوسفؑ کا واقعہ قصہ کے طور پر بیان نہیں ہوا اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قصہ کے طور پر بیان نہیں ہوا ہے بلکہ یہ غیب کی خبریں ہیں یعنی اس واقعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ زندگی کے متعلق خبریں ہیں.چنانچہ جیسا کہ اس سورۃ کی مختلف آیات کی تفسیر میں بتایا گیا ہے حضرت یوسفؑ کی زندگی کے تمام اہم معاملات آنحضرت صلعم کی زندگی میں پورے ہوئے ہیں وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُوْنَ.اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ان مکہ والوں کے پاس نہ تھا جب انہوں نے تیرے متعلق اپنا منصوبہ کیا اور وہ مختلف تدبیریں کرتے تھے.اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ میں آنحضرتؐ کے بھائی مراد ہیں اس جگہ یوسفؑ کے بھائی مراد نہیں بلکہ آنحضرت صلعم کے بھائی مراد ہیں اور بتایا ہے کہ جو سلوک مکہ والوں نے تجھ سے یوسفؑ کے بھائیوں کی مماثلت میں کرنا ہے وہ تیرے اختیار کی بات تو نہیں.پس یہ اخبار غیبیہ کسی انسانی دماغ کا اختراع نہیں کہلا سکتیں بلکہ عالم الغیب خدا کی بتائی ہوئی ہیں.وَ مَاۤ اَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ۰۰۱۰۴ اور خواہ تو( کتنا ہی) چاہے (کہ سب لوگ ہدایت پا جائیں )اکثر لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے.تفسیر.یعنی تیری ذاتی کوشش تو یہی ہوگی کہ تیری قوم تجھ پر فوراً ایمان لائے.لیکن منشائے الٰہی یہی ہے کہ ان سے یوسف کے بھائیوں والے کام ہوں اور تیری خارق عادت ترقی کے بعد وہ ایمان لائیں نہ کہ اس سے پہلے.وَ مَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ١ؕ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ اور تو اس (تبلیغ و تعلیم) کی بابت ان سے کوئی اجر نہیں مانگتا یہ تو تمام جہانوں( اور سب لوگوں) کے لئے( خود) سراسر لِّلْعٰلَمِيْنَؒ۰۰۱۰۵ شرف (کاموجب) ہے.ٍ حلّ لُغَات.اَلذِّکْرُ.اَلتَّلَفُّظُ بِالشَّیْءِ وَاِحْضَارُہٗ فِی الذِّھْنِ بِحَیْثُ لَایَغِیْبُ عَنْہُ.کسی چیز کا
Page 530
منہ سے ذکر کرنا اور اسے ایسے طور پر مستحضر فی الذہن کرنا کہ وہ بھول نہ جائے.اَلصِّیْتُ وَمِنْہُ لَہٗ ذِکْرٌ فِی النَّاسِ.شہرت.اور انہی معنوں میں لَہٗ ذِکْرٌ فِی النَّاسِ کا فقرہ بولتے ہیں کہ فلاں شخص کو لوگوں میں شہرت حاصل ہے.اَلثَّنَاءُ.تعریف.اَلشَّرْفُ.شرف.وَفِی الْقُرْاٰنِ اِنَّہٗ لَذِکرٌ لَّکَ وَلِقَوْمِکَ اور قرآن مجید میں اِنَّہٗ لَذِکْرٌ لَّکَ وَلِقَوْمِکَ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ قرآن مجید کا نزول تیرے اور تیری قوم کے لئے شرف کا موجب ہے.وَالصَّلٰوۃُ للہِ تَعَالٰی وَالدُّعَاءُ اللہ کے حضور دعا چنانچہ انہی معنوں میں یہ فقرہ استعمال ہوتا ہے.اِذَا حَزَبَہٗ اَمْرٌ فَزِعَ اِلَی الذِّکْرِ کہ جب مصیبت کا سامنا ہوا تو اس نے دعا کی طرف جلدی کی.اَلْکِتَابُ فِیْہِ تَفْصِیْلُ الدِّیْنِ وَوَضْعُ الْمِلَلِ.ایسی کتاب جس میں دین کی تفصیل اور شریعت کے اصول ہوں.مِنَ الرِّجَالِ اَ لْقَوِیُّ الشُّجَاعُ الْاَبِیُّ ایسا بہادر شخص جو کسی کا رعب برداشت نہ کرے.مِنَ الْمَطَرِ.اَلْوَابِلُ الشَّدِیْدُ سخت موسلا دھار بارش.مِنَ الْقَوْلِ.الصُّلْبُ الْمَتِیْنُ.پکی بات.(اقرب) تفسیر.حضرت یوسفؑ کی ترقی میں ان کے بھائیوں کی ترقی مقدر تھی جس طرح یوسفؑ کے بھائیوں نے ان کی رؤیا سے یہ سمجھ لیا کہ اس کی بڑائی ہماری ذلت کا موجب ہوگی.حالانکہ ان کی ترقی میں خود بھائیوں کی ترقی مقدر تھی.اسی طرح فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدے ہوئے ہیں ان سے آپ کی قوم کے لوگ ناراض ہوتے ہیں اور ان میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں.حالانکہ وہ اپنی عزت کے لئے ان سے کوئی مدد طلب نہیںکرتا کہ جس سے ان کو یہ خیال ہو کہ اس کی بڑائی میں ہماری کمزوری ہے.پس فرماتا ہے کہ اے ہمارے رسول! تو اگر ان سے مدد کا خواہاں ہوکر اپنی بڑائی کا طالب ہوتا تو ان کے غصہ کی کوئی وجہ ہوتی لیکن تو تو وہ چیز ان کو دیتا ہے جو نہ صرف ان کی عزت کا بلکہ سب دنیا کی عزت کا موجب ہوگی.پس ان کی ناراضگی بے سبب اور ان کا غصہ بلاوجہ ہے.آنحضرتؐ کی حضرت یوسف سے اٹھارھویں مشابہت حضرت یوسفؑ اور رسول کریم ؐ کے مرتبہ میں ایک امتیازی فرق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہت ہے یوسف علیہ السلام نے تو ایک بادشاہ کے ماتحت اپنے بھائیوں کو عزت بخشی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائیوں کو آزاد حکومتوں کا مالک بنا دیا.اور آپ کے
Page 531
دو خسر کہ وہ بھی رشتہ کے لحاظ سے باپ کی جگہ ہوتے ہیں زبردست بادشاہتوں کے مالک ہوئے یعنی حضرت ابوبکر ؓاور حضرت عمرؓ فَتَبَارَکَ اللہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ.وَ كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَ اور آسمانوں اور زمین میں بہت سے نشان (موجود) ہیں جن کے پاس سے یہ لوگ ان سے اعراض کرتے ہوئے گذر هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ۰۰۱۰۶ جاتے ہیں.حلّ لُغَات.کَاَیٍکَاَیِّنْ وَکَاَیٍّ اِسْمٌ مُرَکَّبٌ مِنْ کَافِ التَّشْبِیْہِ وَاَیٍّ الْمُنَوَّنَۃِ وَلِذٰلِکَ جَازَالْوَقْفُ عَلَیْہَا بِالنُّوْنِ وَفِیْہَا لُغَاتٌ اُخْرٰی وَھِیَ کَیْئِنْ وَکَایِنْ وَکَأْ يٍ وَکَاءٍ.وَھِیَ تُوَافِقُ کَمْ فِی خَمْسَۃِ اُمُوْرٍ وَھِیَ الْاِبْہَامُ وَالْاِفْتِقَارُ اِلَی التَّمْیِیْزِ.وَالبِنَاءُ وَلُزُوْمُ التَّصْدِیْرِ.وَاِفَادَۃُ التَّکْثِیْرِ تَارَۃً وَھُوَ الْغَالِبُ نَحْوُ کَاَیِّنْ مِنْ رَّجُلٍ وَالْاِسْتَفْہَامُ اُخْرٰی وَھُوَ نَادِرٌ.کَقَوْلِ اُبَیّ بْنِ ابیْ کَعْبٍ لِابْنِ مَسْعُوْدٍؓ کَاَیّنْ تَقْرَءُ سُوْرَۃَ الْاَحْزَابِ فَقَالَ ثَلَاثًا وَسَبْعِینَ.وَتُخَالِفُہَا فِی خَمْسَةٍ أَمُوْرٍ.اَلْأوَّلُ اِنَّھَا مُرَکَّبَۃٌ وَالثَّانِیْ اِنَّ مُمَیِّزُھَا مَجْرُوْرٌ بِمِنْ غَالِبًا وَالثَّالِثُ اَنَّھَا لَاتَقَعُ اِسْتِفْہَامِیَّۃً عِنْدَ الْجُمْھُوْرِ.وَالرَّابِعُ اَنَّہَا لَاتَقَعُ مَجْرُوْرَۃً.اَلْخَامِسُ اِنَّ خَبَرَھَا لَایَقَعُ مُفْرَدًا.(اقرب) یعنی کَاَیِّنْ کاف تشبیہ اور اَیُّ سے مرکب ہے اور اس کا نون تنوین کا ہے.اسے کئی طرح سے بولا جاتا ہے جس کی حسب ذیل مختلف صورتیں ہیں کَاَیِّنْ.کَایٍّ.کَیْئِنْ.کَأْیٍ.کَاءٍ.کَاَیٍّ پانچ باتوں میں کَمْ کے مطابق ہے اور پانچ میں مخالف اور یہ لفظ پانچ باتو ںمیں لفظ کَمْ کے مطابق ہے اور پانچ باتوں میں اس کے خلاف ہے.جن پانچ باتوں میں کَمْ کی طرح ہے وہ یہ ہیں.(۱) یہ بھی مبہم ہوتا ہے.(۲) اور تمیز کا بھی محتاج ہوتا ہے.(۳) یہ بھی مبنی ہوتا ہے.(۴) اس کو بھی جملہ کے صدر میں لانا ضروری ہے.(۵) عام طور پر کثرت پر دلالت کرتا ہے اور کبھی استفہام کے لئے بھی آتا ہے.جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ابی ابن ابی کعبؓ سے اسی لفظ کے ساتھ یہ سوال کیا تھا کہ سورہ احزاب کی تمہاری قرأۃ کی رو سے کتنی آیتیں ہیں جس کا انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ۷۳ اور جن باتوں میں کم سے کاین اختلاف رکھتا ہے وہ یہ ہیں.(۱) کَاَیِّنْ مرکب ہے اور کم بسیط.(۲) کَاَیِّنْ کے مجرور پر عام طور پر حرف مِنْ آتا ہے اور کم کے
Page 532
مجرور پر اس طرح پر نہیں آتا.(۳) کاین استفہام کے لئے جمہور کے نزدیک نہیں آتا.(۴) کَاَیِّن پر حرف جر یا مضاف نہیں آتا.(۵) اس کی خبر ہمیشہ جملہ ہوتی ہے.تفسیر.کافر اور مومن میں فرق یعنی آسمانوں اور زمین میں بہت سے نشانات ہیں جن کے پاس سے یہ اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے.کافر اور مومن میں یہی فرق ہے کہ مومن تو آنکھیں کھول کر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر اشارہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کافر اندھے کی طرح بڑے سے بڑے نشان کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے حالانکہ حقیقت دونوں کے سامنے ایک ہی ہوتی ہے.اور کافر و مومن کی طاقتیں بھی ایک ہی سی ہوتی ہیں.ہاں جب عذاب آنے شروع ہوتے ہیں تب کفار کی آنکھیں کھلنی شروع ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ حسب مراتب وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھناشروع کرتے ہیں.انبیاء ایک ابتلاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء درحقیقت ایک ابتلاء ہوتے ہیں.کیونکہ ان کے زمانہ میں انسانوں کی طاقتیں اور ان کے اندرونے ظاہر ہوجاتے ہیں جس سرعت یا تاخیر سے انسان مانتا ہے اسی نسبت سے اس کی روحانی طاقتوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے.کیا عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ذرہ ذرہ میں خدا تعالیٰ کے نشانات نظر آنے لگتے ہیں بعض کو لاکھوں بعض کو ہزاروں بعض کو سینکڑوں.اور بعض کو بیسیوں نشان نظر آتے ہیں اور بعض یہی شور مچاتے چلے جاتے ہیں کہ ایک بھی نشان نہیں دکھایا گیا.کوئی نشان نظر آئے تو مانیں.وَ مَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَ هُمْ مُّشْرِكُوْنَ۰۰۱۰۷ اور ان میں سے اکثر (لوگ) اللہ (تعالیٰ) پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حالت میں کہ وہ( ساتھ) ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں.تفسیر.ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر ایسے حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں.ہر کام کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اصل باعث کو نہیں سمجھتے مثلاً زید مر جاتا ہے تو کہتے ہیں فلاں بیماری کی وجہ سے مر گیا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے مرا ہے.اگر کسی کو ترقی کرتا
Page 533
ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی عقل کے زور سے ترقی کر گیا ہے.یہ نادان نہیں دیکھتے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپؐ کی سچی اتباع کی بدولت ترقی کر گیا ہے.آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے بھی تو وہ ان میں موجود تھا اس وقت کیوں ترقی نہ کی؟ کامل توحید بغیر روحانی بینائی تیز نہیں ہوتی اس آیت میں کفار کی نابینائی کی وجہ بتائی ہے.کامل توحید کے بغیر روحانی بینائی تیز نہیں ہوتی.چونکہ عام طور پر لوگوں کے عقیدوں میں شرک کی ملونی پائی جاتی ہے اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے جلوہ کو دیکھ نہیں سکتے اور اگر دیکھ لیں تو پہچان نہیں سکتے کیونکہ شرک تب ہی پیدا ہوتا ہے جب صفات الٰہیہ کو صحیح طور پر نہ سمجھا جائے.شرک کرنے والے کو دائماً اللہ تعالیٰ کی صورت بدلنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے تا جھوٹے معبودوں کو اس کا ہم شکل ثابت کرسکے اور اس کا ایک گہرا اثر اس کے دل پر یوں پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی شکل یعنی اس کی پاک اور مکمل صفات اس کی یاد سے اتر جاتی ہیں اور وہ اس کے جلوہ کو پہچاننے کے قابل نہیں رہتا.مشرک اللہ تعالیٰ کے کاموں کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے چنانچہ مشرک ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو دوسروں کی طرف منسوب کرتا ہے.اگر کسی معین بت یا دیوتا کی طرف منسوب نہیں کرتا تو اسباب کی طرف منسوب کر دیتا ہے.اگر کسی کا خیال اس کے دل سے کلی طور پر محو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا.مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب کفار تباہی کے نشان دیکھتے تو ان کے دوسرے اسباب تلاش کرتے.جب آپؐ کو اور آپ کے صحابہ کو غیر معمولی ترقی پاتے ہوئے دیکھتے تو اس کے بھی مادی اسباب تلاش کرتے اور یہ نہ دیکھتے کہ یہ سب اسباب دعویٰ سے پہلے بھی موجود تھے مگر نتائج ویسے نہ تھے.اَفَاَمِنُوْۤا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تو کیا یہ( لوگ) اس بات سے( محفوظ اور) بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی سخت عذاب تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ۰۰۱۰۸ آجائے یااچانک ان پر وہ گھڑی آجائے (جس کی پہلے سے خبر دی جا چکی ہے) اور انہیں پتہ بھی نہ لگے.حلّ لُغَات.اَمِنَ.اِطْمَأَنَّ.بے خوف اور مطمئن ہو گیا.اَلْاَسَدَ وَمِنْہُ.سَلِمَ.شیر کے حملہ سے محفوظ رہا.پس اَفَامِنُوْا کے معنی ہوئے کیا وہ بے خوف ہو گئے.(اقرب)
Page 534
اَلْغَاشِیَۃُ: یہ غَاشِیٌ کا مؤنث ہے جو غَشِیَ یَغْشٰی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے.غَشِیَ کے معنی ہیں ڈھانپ لیا اور اَلْغَاشِیَۃُ کے معنی ہیں اَلْغِطَاءُ.پردہ.اَلْقِیَامَۃُ لِاَنَّہَا تَغْشٰی بِاَفْزَاعِہَا قیامت کو بھی غاشیہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی گھبراہٹ سب کو ڈھانپ لے گی.نَارُجَہَنَّمَ.جہنم کی آگ.اَلدَّاھِیَۃُ.مصیبت.وَمِنْہُ تَأْتِیْہِ غَاشِیَۃٌ مِنْ عَذَابِ اللہِ.اَیْ نَائِبَۃٌ تَغْشَاہُ اور تَاتِیْہِ غَاشِیَۃٌ مِنْ عَذَابِ اللہِ.انہی مذکورہ بالا معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ عذاب کی کوئی ایسی عام مصیبت آئے جو سب پر چھا جائے.اَلْغَاشِیَۃُ کے معنوں میں یہ بات ملحوظ ہے کہ ایسی مصیبت یا ایسا عذاب ہو جو عام ہو اور سب پر چھا جائے کیونکہ غَشِیَ کے معنے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے ڈھانپ لینے کے ہیں اور ڈھانپ وہی عذاب لیتا ہے جو عام ہو.(اقرب) اَلْبَغْتَۃُ.اَلْفَجْأَۃُ.کسی واقعہ کا ناگہانی طور پر ایسی جگہ سے وقوع پذیر ہونا جہاں سے توقع بھی نہ ہو.وَھُوَ اِمَّا حَالٌ فِیْ تَأْوِیْلِ بَاغِتًا اَوْ مَصْدَرٌ فِی تَأْوِیْلِ اَبْغَتُ بَغْتَۃً.بَغْتَۃً کے استعمال کی دو صورتیں ہیں.اوّل یا تو اس کو حال قرار دیں یعنی ایسی حالت میں کوئی چیز واقع ہوئی کہ اس کا واقعہ ہونا اچانک ہی تھا یا پھر اَبْغَتُ پہلے فعل محذوف ہو گا اور یہ اس کا مفعول مطلق ہوگا جو مصدر کی صورت میں ہوگا.وَالْاَوَّلُ اَصَحُّ پہلی تاویل زیادہ صحیح ہے.(اقرب) شَعَرَ بِہٖ: عَلِمَ بِہٖ.معلوم کیا.لِکَذَا.فَطِنَ لَہٗ.اس کو سمجھا.عَقَلَہُ.اس کو پہچانا.اَحَسَّ بِہٖ.محسوس کیا.(اقرب) ھُمْ لَایَشْعَرُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ ان پر عذاب اتنا اچانک آئے کہ اس کے آنے کا ان کو علم بھی نہ ہوسکے.تفسیر.عذابوں کے متعلق اللہ کی سنت اس آیت میں بتایا ہے کہ چونکہ کفار نشان عذاب کو ہی حقیقی نشان سمجھتے ہیں اس لئے ان پر وہ عذاب بھی آجائے گا مگر سنت اللہ کے مطابق پہلے ادنیٰ عذاب آئیں گے آخر میں فیصلہ کردینے والا عذاب آئے گا.سَاعَةٌ سے مراد فتح مکہ کی ساعت ہے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح عذاب آئے کہ پہلے علاوہ اور عذابوں کے معمولی معمولی شکستیں کفار کو ہوئیں اور آخر فتح مکہ کا واقع ہوا کہ خود مکہ میں لشکر اسلام داخل ہوگیا اور کفار کو ذلت کے ساتھ ہتھیار پھینک دینے پڑے اور اس آیت میں ساعت سے مرادو ہی فتح مکہ کی ساعت ہے کیونکہ اس کے بعد وہ زبردست مشابہت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسفؑ سے تھی پوری ہوئی.یعنی دشمن کو پورے طور پر زیر کرلینے کے بعد آپؐ نے اس کی سب شرارتوں کو بھلا دیا اور بغیر کسی سزا دینے کے کلی طور پر اسے معاف کر دیا.
Page 535
قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ١ؔ۫ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ تو کہہ (کہ) یہ میرا طریق ہے میں( تو) اللہ( تعالیٰ) کی طرف بلاتا ہوں میں اور جنہوں نے (سچے طور پر) میری اتَّبَعَنِيْ١ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۰۰۱۰۹ پیروی اختیار کی ہے (ہم سب) بصیرت پر قائم ہیں اور اللہ (تعالیٰ سب قسم کے نقائص سے) پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں.حلّ لُغَات.اَلْبَصِیْرَۃُ کے معنے ہیں اَلْعَقْلُ عقل.اَلْفِطْنَۃُ.ذہانت.مَایُسْتَدَلُّ بِہٖ.جس کے ذریعہ سے کسی کے متعلق استدلال کیا جائے.اَلْحُجَّۃُ.دلیل.اَلْعِبْرَۃُ یُعْتَبَرُبِھَا.عبرت.اَلشَّاھِدُ.گواہ.وَمِنْہُ عَلٰی نَفْسِہٖ بَصِیْرَۃٌ أَیْ عَلَیْہَا شَاھِدٌ بِعَمَلِھَا.اور عَلٰی نَفْسِہٖ بَصِیْرَۃٌ میںبَصِیْرَۃٌ کے معنی گواہ ہی کے ہیں یعنی نفس کے اعمال پر ایک گواہ مقرر ہے اس کی جمع بَصَائِرُ آتی ہے.(اقرب) اَدْعُوْا اِلَی اللہِ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبعَنِیْ اَیْ عَلٰی مَعْرِفَۃٍ وَتَحَقُّقٍ.آیت اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ١ؔ۫ عَلٰى بَصِيْرَةٍ میں بصیرۃ کے معنے معرفت اور تحقق کے ہیں.(مفردات) تفسیر.هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ سے مراد یعنی جو باتیں اوپر مذکور ہوئی ہیں یعنی آیات اور نشانات سے فائدہ اٹھانا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور شرک سے اجتناب کرنا یہی میرا راستہ ہے.هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ میں گویا اس پہلے مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا ہے.پہلے اس کی طرف ھٰذِہٖ کے ساتھ اشارہ کیا اور پھر اَدْعُوْا اِلَی اللہِ کے ساتھ اس تفصیل کا خلاصہ بیان فرما دیا.نیز پہلے فرمایا تھا مَااَسْئَلُھُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ یعنی تم سے کچھ نہیں مانگتا.اب فرماتا ہے کہ بجائے تم سے مانگنے کے جو کچھ اسے ملا ہے اس میں وہ تم کو شریک کرنا چاہتا ہے.سچے ولی اور جھوٹے ولی میں فرق کیا عجیب فرق ہے سچے ولی اللہ اور جھوٹے ولیوں میں.جھوٹے ولی مخفی اذکار کے مدعی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں اسم اعظم حاصل ہے یا خاص وظیفہ معلوم ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے مگر اس کے برخلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خدا مل گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم کو بھی مل جائے اور اسی کے لئے میں تم کو بلارہا ہوں نہ کہ تم سے کچھ لینے کے لئے.
Page 536
پھر فرمایا کہ تو کہہ دے کہ اس عظیم الشان خدمت میں بھی میں جبر سے کام نہیں لیتا بلکہ دلائل اور براہین سے تم پر حقیقت کو آشکار کرتا ہوں.تعجب ہے کہ اس تعلیم کی موجودگی میں مسلمانوں میں سے بعض جبر کے طریق کو پسند کرتے اور اس طرح اسلام کو دشمنوں کی نگاہ میں رسوا کرتے ہیں.آنحضرت ؐ کا کامل متبع وہ ہے جو آپ کو عقل اور دلیل سے مانتا ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کامل متبع کہلا سکتا ہے جو عقل اور دلیل کے ماتحت آپ کو مانتا ہے.جو مسلمان ایسا ہے کہ وہ اسلام کو یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو، نبیوں کو، قیامت اور حشر نشر کو تقدیر اور فرشتوں کو عقل اور دلائل کے ساتھ سمجھ کر نہیں مانتا بلکہ محض نقل اور تقلید کے طور پر مانتا ہے وہ اس آیت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع نہیں کہلا سکتا.خالی کہہ دینا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں جبکہ نہ قرآن کریم کی صداقت کے دلائل معلوم ہوں نہ ان امور کے جو اس میں مذکور ہیں.کسی کو رسول کریم کا متبع نہیں بنا سکتا.آپؐ کے متبع تو بینا ہوتے ہیں اور ایسا شخص اندھا ہے.فرق صرف یہ ہے کہ دوسرے لوگ دوسری کتب کے اندھے ہیں یہ شخص قرآن کریم کا اندھا ہے.اپنی نسلوںکو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کرناضروری ہے پس اس آیت نے مسلمانوں کی ذمہ داری بہت بڑھا دی ہے.جب تک وہ اپنی نسلوں کو اسلام کی صداقت کے دلائل سے آگاہ نہیں رکھتے اور دلائل بھی وہ جو بصیرت پیدا کرتے ہیں صرف عقلی نہیں بلکہ عقل اور مشاہدہ کا مجموعہ دلائل.اس وقت تک وہ رسول کریمؐ کے متبع نہیں پیدا کرتے بلکہ ایک بے سر فوج پیدا کررہے ہیں.افسوس آج کل مسلمان اس دور انحطاط سے گزررہے ہیں اور اسی وجہ سے ان کے سر کفار کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں بے اثر ہوگئی ہیں.بجائے غیر قوموں میں تبلیغ اسلام کے اسلام سے لوگ مرتد ہونے لگے ہیں.اِنَّالِلہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ.سُبْحَانَ اللہِ کہنے کی وجہ سُبْحٰنَ اللہِ کہہ کر بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو زبردستی مسلمان بنانے کی کیا ضرورت؟ زبردستی کا ایمان بے فائدہ شئے ہے.زبردستی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگوں کی اتباع میں اپنی شان دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے.اس میں کون سی کمی آتی ہے اگر لوگ اس پر ایمان نہ لائیں.پھر جبر وہ کرتا ہے جو دلائل سے نہ منواسکے.اور یہ بھی نقص ہے اور اللہ تعالیٰ نقصوں سے پاک ہے.وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ گو یہ کام جو میں نے اپنے ذمہ لیا ہے بہت بڑا ہے لیکن میں شرک سے کلی پاک ہوں اور میری نگاہ میں یہ کام بڑا نہیں.میں خدا تعالیٰ پرکامل توکل رکھتا اور غیراللہ کو حقیر سمجھتا ہوں.پس
Page 537
خواہ کام کتنا بڑا ہو مجھے اپنی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں.ایمان بغیر بصیرت کے قوم میں شرک پیدا کرتا ہے دوسرے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ جب بھی ایمان بغیر بصیرۃ کے ہوگا قوم میں ضرور شرک پیدا ہوجائے گا.وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ اور تجھ سے پہلے (بھی) ہم (لوگوں کی رہنمائی کے لئے ہمیشہ) انہی (دنیا کی) بستیوں کے رہنے والے مردوں ہی کو الْقُرٰى ١ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ جن پر ہم (اپنی) وحی نازل کرتے تھے رسالت دے کر بھیجتے رہے ہیں تو کیا یہ( لوگ) زمین میں نہیں پھرے تا عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ١ؕ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ دیکھتے (کہ) جو( لوگ) ان سے پہلے (انبیاء کے منکر) تھے ان کا انجام کیسا ہواتھا اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا١ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۰۰۱۱۰ حق میں جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا یقیناً زیادہ بہتر ہے پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے.تفسیر.نبی صرف مردوں میں سے آتے ہیں اس آیت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی صرف مردوں میں سے آتے ہیں.عورت بعض حکمتوں کی وجہ سے اس عہدہ پر مقرر نہیں ہوتی.حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کام کے لئے بنایا ہے.نبوت کا منصب عورت کے دائرہ عمل سے باہر ہے اور چونکہ نبوت کا منصب عورت کے دائرہ عمل سے باہر ہے اس لئے اس پر صرف مردوں کو مقرر کیا جاتا ہے.باقی انعامات چونکہ عورتوں کے دائرہ سے باہر نہیں ان میں وہ مردوں کے ساتھ شریک ہیں.وہ صدّیقہ ہوسکتی ہیں اور ہوتی ہیں.ولیہ ہوسکتی ہیں اور ہوتی ہیں.قانتہ ہوسکتی ہیں اور ہوتی ہیں.غرض سوائے نبوت کے کہ وہ ایک عہدہ ہے باقی سب انعامات ان کو مل سکتے ہیں اور ملتے رہے ہیں.مفہوم آیت کا یہ ہے کہ پہلے بھی نبی انسانوں اور ان میں سے بھی مردوں میں سے آتے رہے ہیں.پس یہ خیال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جیسا انسان ہے نبی کس طرح ہو گیا ایک وسوسہ ہے.اس وسوسہ کے دھوکے
Page 538
میں آکر اپنے آپ کو تباہ نہ کرلینا جو پہلے نبیوں کے دشمنوں سے ہوا وہی اس کے مخالفوں سے ہوکر رہے گا.وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا١ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.آخر میں فرمایا کہ کفار اپنی موجودہ شان و شوکت کا خیال نہ کریں.اس پر غور کریں کہ جو قوم عدل و انصاف کرے اور خدا سے ڈرے انجام کار اسی کی فتح ہوتی ہے اور یہ قاعدہ ایسا بدیہی ہے کہ تعجب ہے لوگ اسے کس طرح بھول جاتے ہیں.دنیا کو ایک وقت تک دھوکا دیا جاسکتا ہے ایک لمبے عرصہ تک دھوکا نہیں دیا جاسکتا.آخر لوگ اپنے نفع نقصان کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے بنی نوع انسان کی بھلائی کرتے ہیں اور اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور اس وقت ظلم کرنے والوں کی حقیقت کھل جاتی ہے.خَیْرٌ کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ خَیْرٌ کے لفظ سے جس کے معنے زیادہ بہتر کے ہوتے ہیں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ موجودہ حالت بھی متقی کی اچھی ہوتی ہے.گو وہ دوسروں کی نگاہوں سے مخفی ہو کیونکہ بے غرضی سے اور صرف خدا تعالیٰ کے لئے کام کرنا دل میں ایک ایسی طاقت پیدا کردیتا ہے کہ باوجود ظاہری کمزوری کے بشاشت اور اطمینان ایسے ہی شخص کو نصیب ہوتا ہے.برخلاف اس کے خدا تعالیٰ سے دوری اور لالچ اور خودغرضی کی حالت عدم اطمینان پیدا کرتی ہے اور حقیقی آرام میسر نہیں آنے دیتی.مومن کی ہر حالت اچھی ہوتی ہے پس ابتدائی حالت بھی مومن ہی کی اچھی ہوتی ہے مگر آخری تو ایسی نمایاں طور پر اچھی ہوتی ہے کہ دشمن کو بھی انکار کی گنجائش نہیں رہتی.حَتّٰۤى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا یہاں تک کہ جب (ایک طرف تو) رسول( ان کی جانب سے) ناامید ہوگئے اور( دوسری طرف) ان( منکروں) کا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ١ؕ وَ لَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ (یہ) پختہ خیال ہو گیا کہ ان سے (وحی کے نام سے) جھوٹی باتیں کہی جا رہی ہیں تو (اس وقت) ان( رسولوں) کے الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ۰۰۱۱۱ پاس ہماری مدد آگئی اور جنہیںہم بچانا چاہتے تھے (انہیں) بچا لیا گیا اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب (ہرگز) نہیںہٹایاجاتا.حلّ لُغَات.کُذِبُوْا.کُذِبُوْاکَذَبَ سے جمع مذکر غائب مجہول کا صیغہ ہے اور کَذَبَہُ الْحَدِیْثَ کے
Page 539
معنے ہیں اِذَا نَقَلَ الْکَذِبَ وَقَالَ خِلَافَ الْوَاقِعِ.اس نے جھوٹی بات بیان کی اور خلاف واقع کہا.کُذِبَ الرَّجُلُ: اُخْبِرَ بِالْکَذِبِ یعنی اسے جھوٹی خبر سنائی گئی.(اقرب) پس ان مذکورہ بالا معنوں کے لحاظ سے وَ ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا کے معنے ہو ںگے کہ کفار نے یہ خیال کرلیا کہ ان سے عذاب کے آنے کے متعلق جھوٹی خبریں سنائی گئیں ہیں.کَذَبَتْہُ نَفْسُہٗ.اِذَا مَنَّتْہُ الْاَمَانِیَ وَخَیَّلَتْ اِلَیْہِ مِنَ الْآمَالِ مَالَا یَکَادُ یَکُوْنُ.کَذَبَتْہُ نَفْسُہٗ کے معنی ہیں کہ اس کو اس کے نفس نے ایسی امیدیں دلائیں جو پوری نہ ہونے والی تھیں.اور اس کے دل میں ایسی آرزوئیں ڈالی گئیں جو بعیداز قیاس تھیں.(اقرب) اس محاورہ کے لحاظ سے ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا کے معنے یوں ہوں گے کہ نبیوں نے خیال کیا کہ شاید ان کے نفسوں نے کلام الٰہی کے غلط معنے سمجھ کر ایسی امیدیں دلادیں جو منشائے الٰہی کے خلاف تھیں.کَذَبَتْکَ عَیْنُکَ.اَرَتْکَ مَالَا حَقِیْقَۃَ لَہٗ آنکھ نے ایسی چیز دکھائی جس کی کوئی حقیقت نہ تھی.(اقرب) اس محاورہ کے رو سے ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا کے معنے یہ ہوں گے کہ نبیوں نے کفار کے حالات سے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ ایمان لے آئیں گے لیکن ان کا خیال بے حقیقت نکلا.قَالَ ابْنُ الْاَنْبَارِیْ اِنَّ الْکَذِبَ یَنْقَسِمُ اِلٰی خَمْسَۃِ اَقْسَامٍ وَالثَّانِیَ اَنْ یَّقُوْلَ قَوْلًا یُشْبِہُ الْکَذِبَ وَلَا یُقْصِدْ بِہٖ اِلَّا الْـحَقَّ وَالرَّابِعُ کَذَبَ الرَّجُلُ بِمَعْنٰی بَطَلَ عَلَیْہِ اَمَلُہٗ وَمَارَجَاہٗ (تاج العروس) ابن انباری نے کذب کی پانچ اقسام بیان کی ہیں اور دوسری قسم یہ بیان کی ہے کہ کذب اس صدق پر بولتے ہیں جو بظاہر جھوٹ نظر آئے اور چوتھی قسم یہ بیان کی ہے کہ کَذَبَ الرَّجُلُ کے معنے ہوتے ہیں اس کی امید درست ثابت نہ ہوئی.پس مندرجہ بالا کذب کے معنوں کے لحاظ سے ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا کی یہ تشریح ہوگی کہ جب نبی کفار کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے جو خبر انہیں دی تھی کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے وہ ذوالمعانی تھی.جو معنے اس کے سمجھے گئے وہ معنے اس کلام کے نہیں تھے.اَلْبَأْسُ.اَلْعَذَابُ.بَاْسٌ کے معنے ہیں عذاب.وَالشِّدَّۃُ فِی الْحَرْبِ.لڑائی میں سختی.وَالْقُوَّۃُ.قوت.وَمِنْہُ اَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْہِ بَأْسٌ شَدِیْدٌ.اَیْ قُوَّۃٌ اور آیت اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ میں بَأْ سٌ کے معنے قوت کے ہیں.وَالْخَوْفُ.خوف.(اقرب) تفسیر.یہ آیت مشکل آیات میں سے قرار دی گئی ہے اس آیت کو نہایت مشکل آیات میں سے قرار دیا گیا ہے کیونکہ بظاہر اس کے یہ معنے بنتے ہیں کہ رسول ناامید ہو گئے اور انہوں نے یہ خیال کرلیا کہ ان سے جو فتوحات کے وعدے کئے گئے تھے وہ جھوٹے تھے اور یہ دونوں باتیں رسالت کی منافی ہیں کیونکہ اسی سورۃ میں
Page 540
آتا ہے اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ(یوسف:۸۸).یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر لوگوں کے سوا کوئی انسان ناامید نہیں ہوتا.پس خدا تعالیٰ کے فضل سے مایوسی نبیوں کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی.اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ نبی خدانخواستہ یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جھوٹ بولا کیونکہ اگر نبی جو معلم اور نمونہ ہوتے ہیں خدا تعالیٰ پر ایسی بدگمانی کریں تو دوسرے لوگوں کو وہ یقین کب میسر آسکتا ہے جو ہر شک و شبہ سے انسان کو بچا لیتا ہے.آیت کے چار معنی لیکن یہ شبہ سطحی نظر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ورنہ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں بلکہ مندرجہ ذیل معانی ہیں: (۱)جس طرح پہلی آیت میں نبیوں اور ان کے مخالفوں کا ذکر تھا اس آیت میں بھی دونوں ہی کا ذکر ہے اور پہلے جملہ میں نبیوں کا ذکر ہے اور دوسرے یعنی ظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا میں کفار کا.اور مراد یہ ہے کہ لوگ شرارت میں بڑھتے چلے گئے اور نبیوں نے خیال کرلیا کہ جس قدر لوگوں کے لئے ایمان مقدر تھا وہ ایمان لاچکے بقیہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اوران کی ہدایت سے مایوس ہو گئے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے.اور باقی بالمقابل کفار بھی جو پہلے ڈر رہے تھے کہ شاید نبیوں کی پیشگوئیاں پوری ہوکر انہیں تباہ کردیں عذاب اور فتح میں دیر ہونے کے سبب سے مطمئن ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اور جو خبریں نبیوں نے دی تھیں جھوٹی تھیں.تو عین اس وقت خدا تعالیٰ کی نصرت آگئی اور ائمۃ الکفر کو تباہ کرکے راستہ صاف کر دیا گیا.یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب انبیاء کے وقت میں ظاہر ہوئی ہر نبی کے زمانہ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ آخری فیصلہ میں اس قدر دیر کردی گئی کہ بظاہر لوگ مطمئن ہوگئے.تب خدا کی نصرت یکدم نازل ہوئی اور نبی اپنے دشمنوں پر غالب آگئے.(۲) کُذِبُوا کا فاعل نفس کو سمجھا جائے اور یہ معنے کئے جائیں کہ انبیاء نے جب کفار کو شرارت میں بڑھتا دیکھا اور ادھر نصرت الٰہی میں دیر دیکھی تو یہ خیال کر لیا کہ انہوں نے کلام الٰہی کے جو معنے سمجھے تھے شاید وہ درست نہ تھے.نصرت الٰہی نے کسی اور رنگ میں نازل ہونا ہوگا.ان معنوں کے رو سے کُذِبُوْا کے معنی غلط امید دلانے کے ہوں گے اور مراد یہ ہوگی کہ نبیوں نے خیال کیا شاید ہمارے نفسوں نے کلام الٰہی کے غلط معنے سمجھ کر ایسی امیدیں دلادیں جو منشاء الٰہی کے خلاف تھیں اور یہ معنی بھی مقام نبوت کے خلاف نہیں کیونکہ نبی الٰہی کلام کے سمجھنے میں اجتہادی غلطی کرسکتا ہے.پس کسی وقت نبی کو یہ خیال ہوجانا کہ جو معنے پیشگوئی کے میں نے سمجھے تھے شاید اس میں اجتہادی غلطی لگ گئی ہو اور نصرت الٰہی کسی اور رنگ میں آنی ہو قابلِ اعتراض امر نہیں.
Page 541
(۳) کُذِبُوْا کا فاعل کفار کو سمجھا جائے اور نائب فاعل بدستور رسولوں کو اور معنے یہ ہوں کہ یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ گزر جانے پر رسولوں کو بقیہ کفار کے ایمان لانے سے مایوسی ہو گئی اور انہوں نے سمجھا کہ ہمیں جو ان کفار کی حالت سے یہ یقین پیدا ہوگیا تھا کہ یہ ایمان لے آئیں گے درست نہ تھا.ان کی درمیانی حالت نے ہمیں دھوکا دیا ان معنوں کے رو سے قَدْ كُذِبُوْا اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ کی تشریح سمجھا جائے گا گویا نبیوں کی مایوسی کے معنے یہ ہیں کہ انہوں نے خیال کرلیا کہ بقیہ کفار کی حالت سے جو ہم خیال کرتے تھے کہ یہ آخر ایمان لے آئیں گے یہ درست نہیں معلوم ہوتا اور یہ حالت بھی حق کو اکثر پیش آتی ہے.بسا اوقات حق کو سن کر درمیانی عرصہ میں منکروں کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ خیال ہوتا ہے اب یہ تسلیم کرلیں گے لیکن پھر شامت اعمال یا ضد یا تکبر کی وجہ سے وہ حق سے دور ہوجاتے ہیں.(۴) قَدْ كُذِبُوْا کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھا جائے اور نائب فاعل نبیوں کو لیکن کذب کے معنے جھوٹ کے نہ لئے جائیں بلکہ بظاہر جھوٹ نظر آنے والے صدق کے لئے جائیں اور یہ معنے جیسا کہ اوپر لکھا جاچکا ہے لغت سے ثابت ہیں اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ نبی کفار کے ایمان سے مایوس ہوگئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ خبر انہیں دی تھی کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے وہ ذوالمعانی تھی.ہم نے جو معنے اس کے سمجھے تھے اور جو اب بظاہر پورا ہوتے نظر نہیں آتے وہ معنے کلام الٰہی کے نہیں تھے وہ ہماری اجتہادی غلطی تھی.خدا تعالیٰ کی مراد کچھ اور تھی جو ہم سمجھ نہیں سکے.تب یکدم اللہ تعالیٰ کی نصرت آگئی اور نقشہ کچھ کا کچھ ہو گیاا ور نبیوں کو غلبہ نصیب ہو گیا.لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ١ؕ مَا كَانَ ان (لوگوں) کے ذکر میں عقل مندوں کے لئے ایک عبرت( کا نمونہ موجود) ہے.یہ ایسی بات (ہرگز) نہیں ہےجو حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ (اپنے پاس سے )گھڑی گئی ہو بلکہ (یہ) اس (کلام الٰہی کی پیشگوئی) کو کامل طور پر پورا کرنے والی ہے جو اس کے
Page 542
تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۰۰۱۱۲ سامنے (پہلے سے موجود) ہے اورہر بات کی پوری تفصیل کرنے والی ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے.حلّ لُغَات.قَصَصٌ قَصَّ عَلَیْہِ الْخَبَرَ والرُّؤْیَا (قَصَصًا) حَدَّثَ بِھِمَا عَلٰی وَجْھِہِمَا وَمِنْہُ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ.قَصَصٌ.قَصَّ.یَقُصُّ کا مصدر ہے جس کے معنے کسی واقعہ کو بعینہا اور صحیح طور پر بیان کرنے کے ہیں.(اقرب) اَلْاَلْبَابُ.اَللُّبُّ خَالِصُ کُلِّ شَیْءٍ.لُبّ ہر چیز کے خالص حصہ کو کہتے ہیں.وَالْعَقْلُ.عقل.اَوِالْخَالِصُ مِنَ الشَّوَائِبِ اَوْ مَازَکٰی مِنَ الْعَقْلِ.ایسی عقل جو تعصب ضد وغیرہ کی ملاوٹوں سے خالص ہو یا اعلیٰ پایہ کی ہو.فَکُلّ لُبّ عَقْلٌ وَلَا عَکْسَ پس جب لبّ کا لفظ بولیں تو اس کے معنے عقل کے کرسکتے ہیں لیکن ہمیشہ عقل کے لفظ پر لبٌّ کا اطلاق نہیں ہوسکتا.وَ مَعْنَا ھَا الْقَلْبُ لبّ کے ایک معنی دل کے بھی ہیں.اس کی جمع اَلْبَاب.اَلُبٌّ اور اَلْبُبٌ آتی ہے.(اقرب) اُوْلُوالاَلْبَاب کے معنے یہ ہوں گے کہ ایسی عقل والے لوگ جو اسے ضد و تعصب وغیرہ سے علیحدہ رکھتے ہیں اور بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں.تفسیر.آنحضرتؐ کی پیشگوئیاں ضرور پوری ہو کر رہیں گی فرماتا ہے اگر یہ لوگ ذرہ بھر بھی غور سے کام لیتے تو پہلے نبیوں کے کلام سے نتیجہ نکال سکتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ ضرور پورا ہوکر رہے گا.کیونکہ آپؐ پہلی پیشگوئیوں کے مطابق آئے ہیں.آنحضرتؐ کا انکار پہلی الہامی کتب کا انکار ہے اگر آپؐ کو جھوٹا خیال کریں گے تو پہلی کتابوں کو بھی جھوٹی ماننا پڑے گا.جیسے مثلاً بائبل وغیرہ میں آپؐ کے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں.اگر آپؐ کے دعویٰ کی صداقت کو تسلیم نہ کیا جائے تو ساتھ ہی ان کتب کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپؐ کے سوا ان کتب کی پیشگوئیوں کا کوئی مصداق نظر نہیں آتا.اگر کوئی کہے کہ شاید آئندہ ظاہر ہو تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب وہ علامات آپؐ کے وجود میں پائی جاچکیں تو آئندہ کسی کے ظاہر ہونے کی امید نہیں رہتی اور اگر فرض کر لیا جائے کہ آئندہ بھی کوئی شخص ایسا آئے گا تب بھی وہ پیشگوئیاں غلط جاتی ہیں کیونکہ جو پیشگوئیاں ایک جھوٹے شخص پر چسپاں ہوگئیں ان کا اعتبار کیا رہا اور آئندہ آنے والے شخص کے متعلق کس طرح سمجھا جاسکے گا کہ وہ ضرور سچا ہے.
Page 543
قرآن مجید ہر دینی ضرورت کوپورا کرتا ہے دوسری دلیل یہ دی کہ آپؐ پر نازل ہونے والی کتاب ہر دینی ضرورت کو پورا کرتی ہے جب سب کچھ اس میں بیان ہوچکا تو اب اور کسی کتاب نے آکر کرنا کیا ہے.یہ ایسی دلیل ہے کہ آئندہ مدعیان شریعت کے دعووں کو بھی باطل کردیتی ہے.بہاء اللہ کے دعوے کے رد میں ایک دلیل مثلاً بہاء اللہ کا دعویٰ ہے کہ وہ نئی شریعت لائے ہیں ان سے سوال کیاجاسکتا ہے کہ وہ کون سی شئے ہے جس کی ضرورت تھی اور قرآن میں نہیں.اس دلیل کے سامنے نہ بہائی اور نہ کسی اور مدعی شریعت کے پیرو ٹھہر سکتے ہیں.قرآن کریم ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ اس کے مطالب سے اعلیٰ مطالب تو بڑی بات ہے اس کے بیان کردہ مسائل کی انواع تک بھی اور کوئی کتاب خواہ نئی ہو یا پرانی نہیں پہنچ سکتی.ھُدًی کی تشریح پھر فرمایا کہ آپؐ کی لائی ہوئی کتاب ھُدًی بھی ہے یعنی صرف تفاصیل بتاکر انسان کو نہیں چھوڑ دیتی بلکہ اسے خدا تعالیٰ تک پہنچاتی بھی ہے اور عقلی مقام سے گذار کر مشاہدہ کے مقام پر لاکھڑا کرتی ہے اور آخری کام آپؐ کی لائی ہوئی کتاب کا یہ بتایا کہ اس کے متبع صرف منہ سے لاف و گزاف نہیں مارتے کہ ہم خدا رسیدہ ہو گئے ہیں بلکہ یہ ان کے لئے رحمت بھی ثابت ہوتی ہے.یعنی انوار الٰہیہ ان پر نازل ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی نصرت اور تائید اس طرح ان کی زندگی کے ہر شعبہ میں نازل ہوتی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی چادر نے ان کو چھپا لیا ہے اور یہ اس کے مقرب ہو گئے ہیں.
Page 559
قبلہ بنانے کی بڑی غرض یہ تھی کہ (نعوذباللہ) یہود خوش ہو کر آپ پر ایمان لے آئیں.اور آپ کی اطاعت کریں.اور آپ اس قبلہ کی طرف اہلِ عرب کو بھی دعوت دیا کرتے تھے.اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَیْنَـمَا تُوَلُّوْ فَثَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ.اس روایت کے یہ الفاظ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذباللہ یہ تبدیلی یہود کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کی تھی واضح طور پر اس امر کا ثبوت ہیں کہ یہ کسی فتنہ پرداز منافق یا کسی خبیث یہودی کی شرارت ہے.اُس نے جب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رُخ کو بدل کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے یہ روایت وضع کر کے مسلمانوں میں پھیلا دی کہ بیت المقدس کی طرف منہ تو صرف اس لئے کیا گیا تھا کہ یہود کو مسلمان بنایا جائے.مگر جب یہ تدبیر کا رگر نہ ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا.اور بعض مفسرین نے بھی اپنی نادانی سے اس وضعی روایت کو اپنی تفسیروں میںدرج کر دیا اور لکھ دیا کہ یہود کی تالیف قلب کے لئے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا تھا.(تفسیر جامع البیان جلد۲ صفحہ۴) پھر اس روایت کے وضعی ہونے کا ایک یہ بھی ثبوت ہے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے صرف محمد ؐ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپؐ کے نام کی بجائے ہمیشہ آپؐ کے رُوحانی مقام سے پکارا کرتے تھے.یعنی محمدؐ کہنے کی بجائے ’’رسول اللہ‘‘ کہا کرتے تھے اور غیر مذاہب کے لوگ ایشیائی دستور کے مطابق آپ کا ادب اور احترام اس طرح کرتے تھے کہ بجائے آپ کو محمدؐ کہہ کر بلانے کے ابوالقاسم کہہ کر بلاتے تھے جو آپ کی کنیت تھی.احادیث میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی مدینہ میں آیا.اور اس نے آکر آپؐ سے بحث شروع کر دی بحث کے دوران میں وہ بار بار کہتا تھا اے محمدؐ بات یوں ہے.اے محمدؐ بات یوں ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بِلا کسی انقباض کے اس کی باتوں کا جواب دیتے تھے مگر صحابہؓ اس کی یہ گستاخی دیکھ کر بے تاب ہو رہے تھے.آخر ایک صحابیؓ سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے یہودی سے کہا کہ خبردار آپؐ کا نام لے کر بات نہ کرو.تم رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم ابو القاسم تو کہو.اس یہودی نے کہا میں تو وہی نام لوں گا جو ان کے ماں باپ نے ان کا رکھا تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپؐ نے صحابہؓ سے فرمایا.دیکھو یہ ٹھیک کہتا ہے.میرے ماں باپ نے میرا نام محمدؐ ہی رکھا تھا.جو نام یہ لینا چاہتا ہے اسے لینے دو اور اس پر غصہ کا اظہار مت کرو.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف محمد کہہ کر کبھی نہیں پکارتے تھے بلکہ اگر کوئی غیر مذہب کا پیرو بھی آپ ؐ کو یَامُحَمَّد کہتا تو وہ انقباض محسوس کرتے.جن صحابہؓ کے اخلاص و محبت کا یہ عالم تھا
Page 566
ایک خاوند اپنی بیوی کو عفیفہ اور صالحہ سمجھتا ہو تو اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے متعلق وہ ہرگز کسی شبہ میں گرفتار نہیں ہوتا بلکہ اُسے جائز طور پر اپنی نسل سمجھتا ہے.یہی بات اللہ تعالیٰ اس جگہ پیش کرتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.یعنی جس طرح ہر انسان اپنی بیوی کی پاکدامنی پر اعتبار کر تے ہوئے اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اپنی اولاد سمجھتا ہے اور کبھی اس واہمہ میں گرفتار نہیں ہوتا کہ شاید یہ کسی اور کی اولاد ہو اسی طرح جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور آپ کی راستبازی کو دیکھا ہے اُن کے لئے آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل خود آپ کا اپنا وجود ہے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (الشعرآء:۲۱۵) تو آپؐ نے مکہ کے تمام قبائل کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ اب باوجود اس کے کہ یہ ایک ناممکن بات تھی کیونکہ اس پہاڑ کے پیچھے میدان تھا اور اس میں کوئی لشکر تو الگ رہا پچاس ساٹھ آدمی بھی نہیں چھپ سکتے تھے.مگر پھر بھی انہوں نے کہا ہم تمہاری بات یقیناً مان لینگے کیونکہ تم نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا.گویا وہ ناممکن بات کو بھی جو آپ کے منہ سے نکلے ماننے کے لئے تیار تھے.اس پر آپ نے فرمایا.اگر تم میری اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہو.تو میں تمہیں بتاتاہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نذیر بنا کر بھیجا ہے اگر تم مجھے نہیں مانو گے تو خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آئو گے(بخاری کتاب التفسیر سورة الشعرآء).اس پر وہ آپ ؐ کو فریبی اور دغاباز کہتے ہوئے واپس چلے گئے.غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن میں اس قدر راستباز اور امین مشہور تھے کہ دشمن بھی اقرار کرتا تھا کہ اس شخص سے بڑھ کر سارے مکہ میں کوئی شخص دیانت دار اور راستباز نہیں.پھر اگر ایک انسان اپنی بیوی کے سو جھوٹ دیکھ کر بھی اپنے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں کرتا توکیا وجہ ہے کہ وہ ایسے شخص پر اعتبار نہیں کرتے جس کا ہر قول سچا اور جھوٹ سے مبرّا رہا ہے.فرماتا ہے کم سے کم بیٹوں جیسا سلوک تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے.بیویوں کی سچائی پر تو دو ۲گواہ بھی نہیں ہوتے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی سچائی پر تمام مکہ شاہد تھا اور دشمن بھی آپ کی راستبازی سے انکار نہیں کرتا تھا.پھر آپؐ کا انکار کیسے درست ہو سکتا ہے.وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.فرماتا ہے ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چُھپا رہا ہے.اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستبازی کا علم ہے.اسے آپ کی دیانت کا علم ہے.اسے آپؐ کی امانت کاعلم ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ اور فریب کے کبھی قریب بھی نہیں گیا.مگر باوجود اس کے وہ حق کو