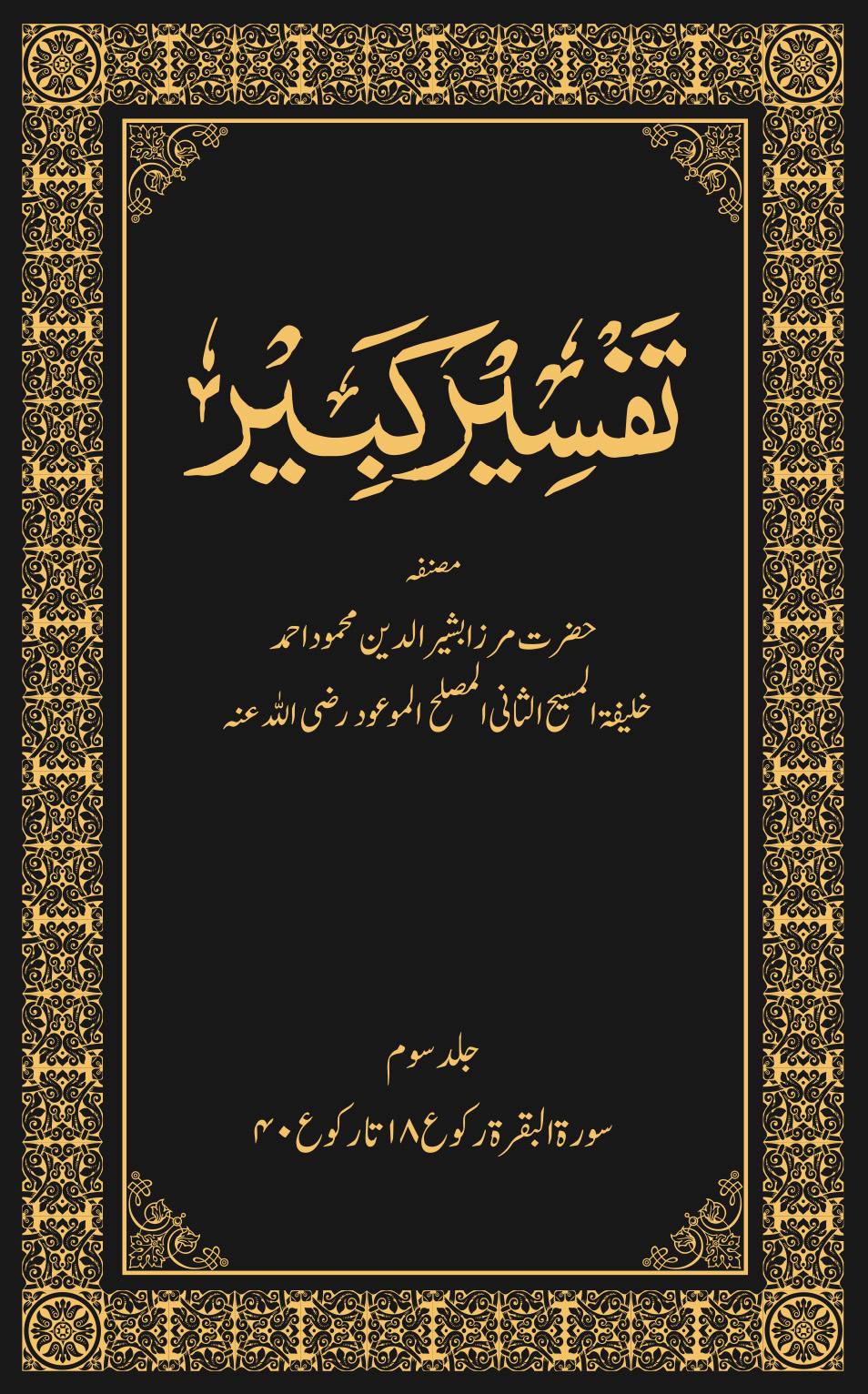Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 3
Content sourced fromAlislam.org
Page 5
وَ لِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ١ؐؕ اور ہر ایک (شخص) کا ایک (نہ ایک) مطمح نظر ہوتا ہے جسے وہ (اپنے آپ پر) مسلط کر لیتا ہے.سو (تمہارا مطمح نظر اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا١ؕ اِنَّ اللّٰهَ یہ ہو کہ) تم نیکیوں (کے حصول) میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو.تم جہاں کہیں (بھی) ہو گے اللہ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍقَدِيْرٌ۰۰۱۴۹ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا.اللہ یقیناً ہر ایک امر پر پورا (پورا) قادرہے.حل لغات.وِجْھَۃٌ وِجْھَۃٌکے تین معنے ہیں (۱)جہت (۲) مِنْہَاجٌ یعنی راستہ اور طریقہ (۳) وہ چیز جس کی طرف انسان توجہ کرے یعنی مقصود.اِسْتَبِقُوْا اِسْتَبَقَ سے جمع کا صیغہ ہے اور اِسْتَبَقَ کے معنے عربی زبان میں اَرَادَ کُلُّ وَاحِدٍ اَنْ یَّسْتَبِقَ الْاٰخَرَ کے ہیں.یعنی ہر ایک نے دوسروں سے آگے نکل جانے کی کوشش کی.تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مطمحِ نظر ہوتاہے جو ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور اسے پورا کرنے کے لئے وہ اپنی تمام مساعی صرف کر دیتا ہے.کبھی وہ تجارت میں ترقی اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے.کبھی زراعت میں ترقی اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے.کبھی سیاسی لحاظ سے اقتدار کا حصول وہ اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے.کبھی سائینس میں ترقی کو اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے.کبھی بیوائوں اور یتامیٰ اور مساکین کی خدمت کو وہ اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے.کبھی دین اور مذہب کی اشاعت کو اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے.غرض ہر شخص کسی نہ کسی مطمح نظر کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس کے حصول کے لئے وہ ہر قسم کی قربانیوں اور جدوجہد سے کام لیتا ہے.نکمّے سے نکمّے انسان کو بھی دیکھ لو.تو معلوم ہوگا کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے.کیونکہ فراغت انسانی فطرت میں داخل ہی نہیں.یہی حال اقوام کا ہے ہرقوم نے اپنا کوئی مقصد قرار دیا ہوا ہوتا ہے.اور وہ اس کے لئے سب کچھ قربان کر دیتی ہے.پس جب ہر انسان دنیا میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے اور کسی نہ کسی امر کے متعلق اُسے شغف ہوتا ہے تو تمہارا بھی ایک مطمحِ نظر ہونا چاہیے.یہ نہ ہو کہ تشتّتِ قومی کے ماتحت کوئی کسی مقصد کو اپنے سامنے رکھ لے اور کوئی کسی مقصد کو.مُوَ لِّیْھَا میں مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے اور اصل عبارت اس طرح ہے کہ وَ لِكُلٍّ
Page 6
وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا وَجْھَہُ.یعنی ہر شخص کی کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے یا ہر شخص کا کوئی نہ کوئی نصب العین ہوتا ہے جس پر وہ اپنی تمام تو جہات کو مرکوز کر دیتا ہے.اور جسے زندگی بھر اپنے سامنے رکھتا ہے اور پورے انہماک اور توجہ سے اسے حاصل کرنےکی کوشش کرتا ہے.مگر لوگ تو اپنے مقاصد اپنے لئے خود تجویز کرتے ہیں.لیکن ہم اُمت محمدیہ پر رحم کرتے ہوئے خود ہی ایک بلند ترین مطمحِ نظر اس کے سامنے رکھتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ.تمہارا مطمحِ نظریہ ہوناچاہیے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو.اس جگہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی تحریک فرما کر اللہ تعالیٰ نے قومی ترقی کا ایک عجیب ُگر بتایا ہے جسے افسوس ہے کہ اس زمانہ میں بالعموم مدّنظر نہیں رکھا جاتا.چنانچہ عام طور پر دیکھا جاتاہے کہ اگر کسی شخص کو نیکیوں میں حصہ لینے کی نصیحت کی جائے یا کسی نیک کام کی ترغیب دلائی جائے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بس غریبوں پر ہی سارا زور ڈالا جاتا ہے امیروں کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں.حالانکہ اگر کوئی بڑا ہے اور وہ نیکیوں میں حصہ نہیں لیتا تو وہ اس کی مثال اپنے سامنے کیوں رکھتے ہیں.انہیں تو اچھے نمونے کی اقتداء کرنی چاہیے اور امارت اور غربت پر بنیاد رکھنے کی بجائے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نیکی اور تقویٰ کس میں پایا جاتا ہے اگر ایک غریب میں نیکی پائی جاتی ہے تو وہ اس امیر کے مقابلہ میں جس کے اندر تقویٰ نہیں خدا تعالیٰ کے حضور لاکھوں گُنا زیادہ بہتر ہے.صحابہؓ کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دفعہ غرباء نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ! جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح امراء بھی نمازیں پڑھتے ہیں.جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں اُسی طرح امراء بھی روزے رکھتے ہیں.جس طرح ہم جہاد کرتے ہیں اُسی طرح امراء بھی جہاد کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ! ایک زائدکام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ صدقہ و خیرات دیتے ہیں اور ہم غربت اور ناداری کی وجہ سے اس میں حصہ نہیں لے سکتے.ہمیں کوئی ایسا طریق بتائیے جس پر چل کر ہم اس کمی کو پورا کر سکیں.آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس دفعہ سُبْحَانَ اللّٰہ اور اَلْحِمْدُ لِلّٰہ اور چونتیس دفعہ اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہہ لیا کرو.وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا.مگر تھوڑے دنوں میں ہی امیروں کو بھی اس کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے بھی تسبیح و تحمید شروع کر دی.اس پر غرباء نے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ! انہوں نے بھی تسبیح و تحمید شروع کر دی ہے اب ہم کیا کریں.آپؐ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق دیتا ہے تو میں اس کو کس طرح روک سکتا ہوں(مسلم کتاب المساجد باب الذکر بعد الصلٰوة).یہ تھی ان کی نیکی اور اس میں تسابق کی روح.اسی طرح بجائے اس کے کہ انسان اعتراض کرے اور کہے کہ فلاں سے یہ کام کیوں نہیں کروایا جاتا.اُسے چاہیے کہ خود اس میں حصہ لے اور دوسروں سے آگے
Page 7
بڑھنے کی کوشش کرے.غرض دنیا میں ہر شخص کا ایک مطمحِ نظر ہوتا ہے.کسی کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے.کسی کو عیش و عشرت کا شوق ہوتا ہے.کسی کو تجارت کا شوق ہوتاہے.کسی کو اچھے لباس کا شوق ہوتا ہے.کسی کو غیبت اور بدگوئی کا شوق ہوتا ہے.کسی کو لڑائی جھگڑے کا شوق ہوتا ہے.غرض کوئی انسان نہیں جس نے اپنے لئے کسی نہ کسی چیز کے حصول کوا پنا مقصد قرار نہ دیا ہوا ہو.غریب سے غریب اور جاہل سے جاہل بھی اپنے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے کسی کا مقصد چودھرایت حاصل کرنا ہوتا ہے.کسی کا مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہوتا ہے.کسی کا مقصد سیاسی اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے.فرماتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی مقصد ہر انسان کے سامنے ہوتا ہے تو پھر تم وہ بات کیوں نہ کرو جس میں سب اچھی باتیں آجائیں.تمہیں یہ تہیّہ کر لینا چاہیے کہ کوئی خوبی ایسی نہ ہو جس میں دوسرا ہم سے آگے نکل جائے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک دفعہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا.جب وہ جُدا ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوا آپ اِس خیال سے کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور ذریعہ سے اس کی خبر ہوئی تو آپ کو تکلیف ہو گی فوراً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ! آج ابوبکرؓ سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا جس کا مجھے افسوس ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر غصہ آگیا اور آپ نے فرمایا تم لوگ کیوں اُسے تکلیف دینے سے باز نہیں آتے؟ جب تم لوگ اسلام کا مقابلہ کر رہے تھے تو وہ مجھ پر ایمان لایا تھا.اور اس نے میرا ساتھ دیا تھا.حضرت عمرؓ ابھی معذرت ہی کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی خیال آیا کہ شاید حضرت عمرؓ میرے متعلق کوئی ایسی بات نہ کردیں جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو ں اس لئے وہ بھی دوڑ کر آئے کہ میں چل کر حقیقت حال بتائوں.کہ میرا نہیں بلکہ عمرؓ کا قصور تھا.مگر جونہی آپ دروازہ میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ معذرت کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو ناراض ہو رہے ہیں.حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اُسی وقت دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کیا.یا رسول اللہ! فِدَاکَ اَبِیْ وَاُمِّیْ.قصور میرا ہی تھا.عمر کا قصور نہیں تھا.اس طرح آپ نے حضرت عمرؓ پر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دُور کرنے کی کوشش کی(بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی باب قول النبی لوکنت متخذا خلیلا....).یہ تھی اُن کی نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی رُوح کہ قصور حضرت عمرؓ کا ہے مگر معافی حضرت ابوبکرؓ مانگ رہے ہیں تاکہ حضرت عمرؓ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوں.درحقیقت اسلام اور دوسرے مذاہب میں جہاں اور بہت سے امتیازات ہیں جو اُس کی فضیلت کو نمایاں طور پر ثابت کرتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے مذاہب صرف نیکی کی طرف بلاتے ہیں مگر اسلام
Page 8
استباق کی طرف بلاتاہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.دنیا میں ہر قوم نے ایک ایک طرف اختیار کر لی ہے اور نیکی کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا ہے.وہ کہتے تو یہی ہیں کہ ہم نیکی کی طرف لے جاتے ہیں لیکن واقعہ میں ایسا نہیں کرتے.پس اُن کے اور اطراف کو اختیار کرلینے کی وجہ سے نیکی کی طرف بالکل خالی رہ گئی ہے.تم اس کو لے لو اور اوّل تو نیکی اختیار کرو اور پھر نیکیوں میں استباق کرو.اور دوسروںسے آگے بڑھنے کی کوشش کرو.اللہ تعالیٰ نے یہاں استباق کا لفظ رکھا ہے جس میں بظاہر سرعت اور تیزی نہیں پائی جاتی اس لئے کہ اگر دو آدمی سُست روی سے جا رہے ہوں اور ایک ان میں سے کسی قدر آگے بڑھ جائے تو لغت کے اعتبار سے اس نے استباق کر لیا.اسی طرح ہر کام میں تھوڑا سا بڑھنے کا نام استباق رکھا جاسکتا ہے لیکن دراصل اس لفظ میں انتہا درجہ کی سرعت اور تیزی سے آگے بڑھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے.کیونکہ ہر شخص کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ استباق کرے.اب اگر ایک شخص کوشش سے کچھ آگے بڑھے تو دوسرے کے لئے بھی حکم ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھے.اور جب وہ اس سے آگے بڑھے گا تو پھر پہلے کو وہی حکم آگے بڑھنے کے لئے تیار کر دے گا.غرض ہر ایک کے لئے استباق کا حکم ہے.اور ہر شخص جہاں تک انسانی طاقت میں ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرےگا اور اس طرح اُس کی نیکیوں میں ترقی کرنے کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی.یوں تو فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰتِ کی بجائے بعض اور الفاظ بھی رکھے جا سکتے تھے مثلاً فَاسْعَوْا بھی رکھا جاسکتا تھا.مگر جو حقیقت فَاسْتَبِقُوْا میں رکھی گئی ہے وہ کسی اور میں نہیں آسکتی تھی.درحقیقت اس جگہ قرآن کریم اسلام اور دیگر مذاہب کا مقابلہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام مذاہب خیرات کی طرف سے غافل ہیں اور خیرات کی حقیقت سے ناواقف ہیں پس اس وقت مسلمانوں کے لئے موقعہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں.یہ لفظ ایسا جامع ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی مقصد اور مدعا کی طرف دوڑنے اور اُسے جلدی سے حاصل کرنے کا مفہوم کسی اور لفظ سے ادا ہی نہیں ہو سکتا.ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوڑے مگر پوری طاقت سے نہ دوڑے.جلدی کرے مگر جس قدر چاہیے اس قدر جلدی نہ کرے لیکن استباق کے حکم کا اس وقت تک پورا ہونا ناممکن ہے جب تک کہ پورے زور اور پوری طاقت سے کام نہ لیا جائے.اس لئے کہ جب ایک شخص سے دوسرا بڑھتا ہے تو اس کو بھی تو حکم ہے کہ آگے بڑھو.اس لئے وہ اس سے زیادہ تیزی سے بڑھے گا.پھر پہلے کے لئے حکم آجائے گا کہ تم آگے بڑھو.اور وہ اس سے زیادہ تیزی اختیار کرےگا.حتیّٰ کہ جس قدر کسی میں طاقت اور ہمت ہوگی وہ سب اس میں صرف کر دےگا.پس استباق بظاہر اپنے اندر تیزی اور دوڑنے اور جلدی کرنے کے معنے نہیں رکھتا مگر حقیقت میں یہ لفظ اس قدر تیزی پر دلالت کرتا ہے کہ جس قدر کسی انسان کی طاقت میں ہوتی ہے.دوسرے
Page 9
مذاہب والے کہتے ہیں کہ نیکی کرو.مگر اسلام کہتا ہے کہ نیکی کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو.یہ کام کوئی معمولی کام نہیں.ایک دو کامقابلہ ہو تو کوئی بات بھی ہے لیکن یہاں تو لاکھوں کا مقابلہ ہے جب ایک دو کے مقابلہ میں بھی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے تو جہاں لاکھوں میں مقابلہ ہو وہاں کتنی بڑی تیاری کی ضرورت ہو گی.گھوڑدوڑ میں دیکھ لو کتنی تیاری کی جاتی ہے.جب لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں تو کتنی کوشش اور تیاری کرتے ہیں لیکن جہاں لاکھوں اور کروڑوں افراد ہوں وہاں تو جتنی تیاری کی ضرورت ہو سکتی ہے اسے ہر انسان آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے.غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی شناخت کا یہ معیار بیان فرمایا ہے کہ وہ تسابق اختیار کرتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش یقیناً ہر قوم کے معیار کو اتنا بلند لے جاتی ہے کہ اس کا انسان قیاس بھی نہیں کر سکتا.جب کبھی نیکی دنیا سے مفقود ہو جائے یا جب کبھی نیکی میں آگے بڑھنے کی رُوح مفقود ہو جائے اس وقت قوم یا تو مرنا شروع ہو جاتی ہے یا گرنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جب تک تسابق کی روح کسی قوم میں قائم رہے.اس وقت تک خواہ وہ کتنی بھی ذلّت میں پہنچی ہوئی ہو اور کتنی بھی گِری ہوئی ہو پھر بھی اپنی چمک دکھلاتی چلی جاتی ہے اور اس کے لئے موقعہ ہوتا ہے کہ وہ پھر آگے بڑھے.ہمارے قریب کے بزرگوں میں سے ایسے زمانہ میں جب مسلمانوں پر ایک قسم کے تنزل کی حالت آگئی تھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ تسابق کی وجہ سے ان لوگوں کے واقعات سن کر انسان کے دل میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے.سید اسمٰعیل صاحب شہید جو تیرھویں صدی میں گذرے ہیں حضرت سیداحمد صاحب بریلوی کے مرید تھے.اور سید احمد صاحب بریلوی سکھوں سے جہاد کرنے کے لئے پشاور کی طرف گئے ہوئے تھے.سید اسمٰعیل صاحب کسی کام کے لئے دہلی آئے ہوئے تھے.جب دہلی سے واپس جاتے ہوئے کیمبل پور کے مقام پر پہنچے تو کسی نے ان سے ذکر کیا کہ اس دریا کو یہاں سے تیر کر کوئی شخص نہیں گذر سکتا.اس زمانہ میں صرف فلاں سکھ ہے جو گذر سکتا ہے مسلمانوں میں سے کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں.وہ وہیں ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ اچھا ایک سکھ ایسا کام کرتا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا.اب جب تک میں اس دریا کو پار نہ کر لوںگا میں یہاں سے نہیں ہلوںگا.چنانچہ وہیں انہوں نے تیر نے کی مشق شروع کر دی.اور چار پانچ مہینہ میں اتنے مشّاق ہو گئے کہ تیر کر پار گذرے اور پار گذر کر بتا دیا کہ سکھ ہی اچھے کام کرنے والے نہیں بلکہ مسلمان بھی جب چاہیں ان سے بہتر کام کر سکتے ہیں.اس تسابق کی روح کو جب بھی ہم اپنے سامنے لاتے ہیں ہماری روحوں میں ایک بالیدگی پیدا ہو جاتی ہے.ہمارے دلوں میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے.اور ہمارے دماغوں میں عزم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مخالف یا مدِّ مقابل یا رقیب سے کسی صورت میں بھی دبیں گے نہیں.اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ ہم نیکیوں کے مقابلہ
Page 10
میں سست ہوں.بلکہ نیکی کے میدان میں اپنے باپ اور بھائی سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے.اسی طرح قومی وقار اور اعزاز کو ہمسایہ قوموں سے آگے بڑھانے کے لئے علمی، اقتصادی، سیاسی اور اخلاقی امور میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے.قرآن کریم نے فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰتِ کہہ کر اور ایک جگہ وَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا (النازعات:۵) فرما کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے.تمہارا فرض ہے کہ اس مسابقت میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرو.ہماری جماعت کو بھی چاہیے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے نفس کو ٹٹولتا رہے اوردین کے ساتھ ایک گہری محبت اور شیفتگی پیدا کرنے کی کوشش کرے.اور سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے بس یہی ایک مقصد اپنے سامنے رکھے کہ ہم نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے.جب تک یہ روح ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی اُس وقت تک ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے.اس آیت کا پہلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو اپنا مقصد قرار دیا ہوا ہے چنانچہ فرمایا تھا وَلَئِنْ اٰتَیْتَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتٰبَ بِکُلِّ اٰیَۃٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَکَ یعنی اگر تو اہل کتاب کے پاس ہر قسم کا نشان بھی لے آئے تب بھی وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریںگے گویا خواہ ان کے ہاتھ سے خدا جائے یا اس کا رسول جائے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ضرور کرنی ہے.اور یہ نتیجہ ہے اس امر کا کہ انہوں نے اپنا کوئی اعلیٰ مقصد قرار نہیں دیا ہوا.پس چاہیے کہ تم اپنا ایک اعلیٰ مقصد قرار دے لو مگر یہ یاد رکھو کہ کوئی ایک نیکی اپنا مقصد قرار دے لینا کافی نہیں بلکہ الخیرات یعنی سب نیکیوں کو اپنا مقصد قرار دو اور جب بھی تمہیں کوئی نیک بات معلوم ہو بلا کسی اور خیال کے اُس کوحاصل کرنے کی کوشش کرو.اور اس سے دُور رہنے کو ہلاکت سمجھو.اور دوسری بات یہ مدِّ نظر رکھو کہ نیکی کے حصول کے وقت تسابق کو مدِّنظر رکھو یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو.اور تیسری بات یہ مدِّنظر رکھو کہ اگر تمہارا قدم دوسروں کی سُستی کی وجہ سے یا تمہاری چستی کی وجہ سے آگے پڑ رہا ہے تو دوسروں سے صرف بعض نیکیوں میں آگے رہنے کو کافی نہ سمجھو بلکہ جس قدر جلد ہو سکے ہر قسم کی خیرات کے حصول کے لئے قدم بڑھائو.اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی توجہ دلائی ہے کہ کَلِمَۃُ الْحِکْمَۃُ ضَا لَّۃُ الْمُؤْمِنِ اَخَذَ ھَا حَیْثُ وَجَدَ ھَا (ابن ماجہ کتاب الزھد باب الحکمۃ ) یعنی حکمت کی بات مومن کی ایک گمشدہ متاع ہوتی ہے وہ جہاں سے بھی ملے اسے فوراً لے لیتا ہے.اس حدیث میں ایک تو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مومن کوئی بات بھی بغیر حکمت کے نہیں کرتا.تمام خوبیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور تمام نیکیاں اُس کے اندر جمع ہوتی ہیں.اور دوسرے اس امر کی نصیحت کی گئی ہے کہ اُسے جب بھی کوئی حکمت
Page 11
کی بات نظر آئے تو وہ یہ دیکھے بغیر کہ یہ کلمہ حکمت کسی کافر کے منہ سے نکلا ہے یا منافق کے منہ سے فوراً اسے اپنی کھوئی ہوئی چیز سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرے.گویا جس طرح ایک کھویا ہوا بچہ اُسے نظر آجائے تو وہ فوراً اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح وہ بھی لپک کر اس خوبی کو لے لے اور کہے کہ اوہو! یہ تو میری ہی چیز تھی افسوس کہ اسے کافر یا منافق لے گیا.اب یہ میرا کام ہے کہ میں اپنی گمشدہ متاع واپس لوں اور اس خوبی کو اپنے اندرپیدا کرنے کی کوشش کروں.دُنیا میں بہت سی خرابیاں محض اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ جس کسی کے پاس جتنی نیکی ہوتی ہے وہ اسی پر فخر کرنے بیٹھ جاتا ہے اور مزید خوبیاں اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتا اوراگر دشمن میں اُسے کوئی خوبی نظر آتی ہے تو کینہ اور بُغض اور حسد کی وجہ سے وہ اسے بھی بُرا قرار دینے کی کوشش کرتاہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس کے ایسا کرنے سے دشمن کا تو کوئی نقصان نہیں اس کے پاس تو وہ خوبی ہے ہی نقصان اس کا اپنا ہے.کیونکہ بُغض کی وجہ سے وہ اس خوبی کو حاصل نہیں کرسکے گا پس مومن کا کام ہے کہ وہ ہر خوبی اپنے اندر پیدا کرے.اور ہر خوبی میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے.یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے اس طرح حسد کی بنیاد رکھی ہے کیونکہ امورِ دینیہ اور امور دنیویہ میں یہ مقابلہ ضروری ہے اس کے بغیر کامل ترقی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی.تمام ترقی کی بنیاد ہی مقابلۂ اقوام و افراد ہے.خود غرضی کی جڑ شریعت اسلام نے کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ(آل عمران:۱۱۱)کہہ کر اُکھاڑ دی ہے کیونکہ مومن کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ جس درجہ تک پہنچے اس پر فوراً دوسروں کو بھی پہنچائے.کیونکہ اس کی غرض ہی دوسروں کو نفع پہنچانا ہے.اسی طرح فرماتا ہے.وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ١ؕ وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ( اٰل عمران :۱۰۵) یعنی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کاکام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے.اور اچھی باتوں کی تعلیم دے اور بُرائیوں سے روکے.اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں.پس جس خیر کو بھی مومن حاصل کرےگا وہ فوراً دوسروں کو بلائے گا کہ جلد آئو اور اس چیز کو حاصل کرو.گویا مومنوں کا یہ فرض ہے کہ وہ جب آگے بڑھیں تو پچھلوں کو بھی کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لیں.پھر آگے بڑھیں تو جو لوگ پیچھے رہ جائیں ان کو دوبارہ کھینچ کر اپنے ساتھ شامل کر لیں.پھر دوڑیں اور اس طرح جو پیچھے رہ جائیں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور پھر سارے مل کر نیکیوں کے میدان میں دوڑیں.اس پر پھر جو اُن میں سے آگے نکل جائیں وہ پچھلوں کو کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لیں.اور اس طرح ایک دوڑ جاری رہے.نیکیوں میں سبقت لے جانے والے سبقت لے جائیں اور پیچھے رہ جانے والوں کو ساتھ ملالیں.پھر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور پھر
Page 12
پچھلوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور یہی عشق کی کیفیت ہوتی ہے.خدا تعالیٰ مومنوں سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس کے پاس اکیلے نہ آئیں بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لیتے آئیں.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر کی طرف روانہ کرتے وقت کہا تھا کہ تم نے اکیلے نہیں آنا بلکہ بن یا مین کو بھی ساتھ لیتے آنا.اسی طرح خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تم میرے پاس دوڑ کر آنا اور اکیلے نہ آنا بلکہ میرے دوسرے روحانی بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر آنا.مومن دوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے وہاں میں اُسے کیا جواب دوں گا اس لئے وہ دوسروں کو بھی کھینچ کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے.غرض کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اور وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ نےحسد اور خود غرضی کی جڑ کاٹ دی ہے کیونکہ مومن جس خیر کو خود حاصل کرےگا وہ فوراً اس میں شامل کرنے کے لئے دوسروں کو بھی بُلائےگا اور اس طرح نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جہاں ایک لطیف مقابلہ جاری رہےگا وہاں خود غرضی اور حسد کا بھی کوئی شائبہ دکھائی نہیں دےگا.یہ کیا ہی لطیف مقابلہ مبادرہ اور پھر مجاذبہ ہے.اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا.فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو گے آخر ایک دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے اپنے پاس لے آئےگا اور تمہیں اپنی سستیوں اور غفلتوں اور لوگوں کو نیکیوں کی دوڑ میں پیچھے چھوڑنے کا جواب دینا پڑے گا.پس اُس دن کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے وہ تم سے ضرور پوچھے گا کہ جب میں نے تمہیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی تھی تو تم نے اسے دوسروں تک کیوں نہ پہنچایا اور نیکیوں کی دوڑ میں تم نے دوسروںسے سبقت لے جانے کی کیوں کوشش نہ کی پس تم اُس دن کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو اور اپنے اعمال کا جائزہ لو.ایسا نہ ہو کہ اس دن تمہیں شرمندگی لاحق ہو اور خدا تعالیٰ کے حضور تم مجرم قرار پائو.اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تم اس مقصد کو ناقابلِ حصول مت سمجھو.جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری قسمت میں کہاں رکھا ہے کہ ہم اتنا بڑا مقام حاصل کر سکیں.وہ ہمت سے کام لینا ترک کر دیتے ہیں اور ہاتھ پائوں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ہمارے لئے مقدر کیا ہے وہی کچھ ہمیں ملے گا.حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی طاقتیں رکھی ہیں وہ نیکیوں میں خود بھی بڑھ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھینچ کر اپنے ساتھ شامل کر سکتا ہے.یہ کام ناممکنات میں سے نہیں ہے.
Page 13
وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ١ؕ اورتو جس جگہ سے بھی نکلے اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف پھیر دے اور یہ (حکم) وَ اِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ١ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا یقیناً تیرے رب کی طرف سے (آئی ہوئی) صداقت ہے اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر تَعْمَلُوْنَ۰۰۱۵۰وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ نہیں ہے اور ُتو جس جگہ سے بھی نکلے اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ١ؕ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ پھیر دے اور تم (بھی) جہاں کہیں ہو اپنے منہ اس کی طرف کیا کرو.شَطْرَهٗ١ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ١ۙۗ اِلَّا الَّذِيْنَ تا ان لوگوں کے سوا جو ان (مخالفوں) میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں (باقی) لوگوں کی طرف سے تم پر الزام ظَلَمُوْا مِنْهُمْ١ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِيْ١ۗ وَ لِاُتِمَّ نِعْمَتِيْ نہ رہے سو تم ان (ظالموں) سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو (یہ حکم میں نے اس لئے دیا ہے کہ تم پر لوگوں کا الزام عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَۙۛ۰۰۱۵۱ نہ رہے) اور تاکہ مَیں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پائو.حلّ لُغات.خَرَجْتَ عربی زبان میں خَرَجَ کا لفظ نکلنے کے علاوہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ(۱) جب خَرَجَ عَلَیْہِ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں.بَرَزَ لِقِتَالِہٖ وہ اس سے جنگ کرنے کے لئے نکلا.اگر اس آیت میں یہ معنے مراد لئے جائیں تو یہ لفظ جنگ کرنے کے معنوں میں استعمال ہو گا.(۲) پھر اس لفظ کے معنے اطاعت ترک کر دینے کے بھی ہوتے ہیں.چنانچہ خَرَجَتِ الرَّعِیَّۃُ عَلَی الْوَالِیْ کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ
Page 14
خَلَعَتِ الطَّاعَۃَ یعنی رعیت نے والی کی اطاعت چھوڑ دی اور بغاوت اختیار کر لی.(۳) اسی طرح خَرَجَ الْوَالِیْ عَلَی السُّلْطَانِکے معنے ہوتے ہیں تَمَــرَّدَ یعنی والی نے سلطان کے خلاف سرکشی کی.(اقرب) قتال کے معنوں میں قرآن کریم میں بعض دوسرے مقامات پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے.چنانچہ سورۃ توبہ آیت ۸۳ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآىِٕفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّ لَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا١ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَیعنی اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو اُن میں سے ایک گروہ کی طرف لوٹا لائے اور وہ لوگ تجھ سے خروج کی یعنی کسی آئندہ جنگ میں شامل ہونے کی اجازت مانگیں تو تُو اُن سے کہہ دے کہ تم کو کبھی بھی آئندہ ہمارے ساتھ جنگ پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی.اور کبھی بھی تم دشمن سے میرے ہمراہ ہو کر لڑنے نہیں پائو گے.کیونکہ تم پہلی دفعہ پیچھے بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے.پس آئندہ ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھ رہا کرو.یہاں خروج بمعنے قتال آیا ہے جیسا کہ لَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِیَ عَدُوًّا سے واضح ہے.حُـجَّۃ اس لفظ کے معنے عربی زبان میں اس دلیل کے ہوتے ہیں جو انسان کو دوسرے پر غالب کر دے.قَالَ الْاَ زْھَرِ یُّ اَلْوَجْہُ الَّذِیْ یَکُوْنُ بِہِ الظَّفَرُ یُسَمّٰی حُـجَّۃً.(لسان العرب) وَفِیْ اَبِی الْبَقَائِ وَمِنْ حَیْثُ الْغَلَبَۃِ عَلَی الْخَصْمِ یُسَمّٰی حُـجَّۃً ( کلّیاتِ ابی البقاء).یعنی ازہری کہتے ہیںکہ وہ دلیل جس سے انسان کو کامیابی حاصل ہو اسے حجت کہتے ہیں اور کلیات ابوالبقاء میں لکھا ہے کہ اس کا نام حـُجَّۃٌ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کے ذریعے دشمن پرغلبہ حاصل ہوتا ہے.غالب کر دینے والی دلیل کے معنے میںحجۃ کا لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے.جیسے دجال کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنْ یَخْرُجْ وَاَنَا فِیْکُمْ فَاَنَا حَجِیْجُہٗ (ابن ماجہ کتاب الفتن باب فتنة الدجّال و خروج عیسَی بن مریم).یعنی اگر دجال نے خروج کیا اور میں تم میں موجود ہوا تو میں وہ دلائل اس کے سامنے پیش کروںگا اور ایسی باتیں اس کے سامنے رکھوں گا کہ و ہ شکست کھا جائے گا.اس حدیث سے ایک طرف تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حجت کے معنے اس دلیل کے ہوتے ہیں جس سے دشمن ہار جائے اور شکست کھا جائے.اور دوسری طرف اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال سے تلوار کی لڑائی نہیں ہو گی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اُس سے بحث کر کے دلائل کے لحاظ سے فتح پائوںگا نہ کہ تلوار کے زور سے.پس معلوم ہوا کہ دجال پر حجت کے لحاظ سے غلبہ حاصل کیا جانا مقدر ہے نہ کہ تلوار کے ساتھ.حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر غیر احمدی علماء اعتراض کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے دجال سے تلوار کے ساتھ جنگ کر کے اس کو ہلاک
Page 15
نہیں کیا بلکہ جہاد بالسیف قطعی طور پر منسوخ کر دیا.حالانکہ اگر وہ احادیث پر تھوڑا سا بھی غور کریں تو ان پر واضح ہو جائے کہ دجال پر دلائل کے ذریعے ہی غلبہ حاصل کرنا ضروری ہے ورنہ تلوار کے ذریعہ دجال کی ہلاکت کی خبر کسی حدیث میں نہیں دی گئی.حُـجَّۃٌ کا لفظ کبھی غلط یا کمزور دلیل کے معنے میں بھی استعمال ہو جاتا ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی قرینہ موجو د ہو.جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ(الشورٰی:۱۷) یعنی ان کی دلیل ان کے رب کے حضور باطل اور ضائع ہونےوالی ہے.حُـجَّۃٌ کے معنے خالص دلیل کے بھی ہوتے ہیں جیسے قرآن کریم میں آتا ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖۤ(البقرة: ۲۵۹) یعنی کیا تجھے اس شخص کا حال معلوم نہیں جس نے ابراہیم ؑ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کی تھی.یہاں صرف دلیل کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ دونوں فریق غالب نہیں ہو سکتے.اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اِلَّا کبھی لٰکِنْ کے معنے میں بھی آتا ہے چنانچہ عربی محاورہ ہے مَالَکَ عَلَیَّ حُـجَّۃٌ اِلَّا اَنْ تَظْلِمَنِیْ اَیْ مَالَکَ عَلَیَّ حُـجَّۃٌ وَلٰکِنَّکَ تَظْلِمُنِیْ(بحر محیط و تفسیرفتح البیان زیر آیت ھٰذا) یعنی تجھے مجھ پر کوئی حجت تو حاصل نہیں ہاں اگر ُتو مجھ پر ظلم کر ے اور خواہ مخواہ اپنے باطل دعوے کو سچا سمجھے تو اور بات ہے.(۲) کبھی اِلَّا عاطفہ ہوتا ہے یعنی وائو کے قائم مقام ہو کر آتا ہے اور ماقبل کو مابعد کے ساتھ شریک کرتا ہے جیسے لِئَلَّا یَکُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّۃٌ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مَنْھُمْ اور لَا یَخَافُ لَدَ یَّ الْمُرْسَلُوْنَ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْئٍ میں ہے(مغنی اللبیب)اس لحاظ سے اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا کے معنے ہوں گے وَلَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اور اِلَّا مَنْ ظَلَمَ کے معنے ہوں گے وَلَا مَنْ ظَلَمَ.یعنی اس صورت میں اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا کے معنے یہ ہوں گے کہ نہ معقول اور نہ غیر معقول لوگ کوئی بھی ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتے جس سے وہ لوگوں میں مسلمانوں کے حق پر ہونے کو مشتبہ کر سکیں.تفسیر.وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ کے معنے مفسرین نے یہ کئے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو ہر حالت میں اپنا قبلہ مسجدحرام کو ہی رکھو اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے حکم سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ قبلہ صرف مدینہ والوں کے لئے ہی ہو باقی لوگوں کے لئے نہ ہو اس لئے خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جہاں کہیں سے بھی نکلو اپنے منہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو.لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواہ اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہو خواہ تمام مسلمانوں کو اس کے معنے قبلہ کی طرف منہ کرنے کے ہو ہی نہیں سکتے.اوّل تو اس لئے کہ وہ نمازیں جو کسی شہر یا گائوں میں رہتے ہوئے ادا کی جاتی ہیں شہر سے نکلتے وقت کی نمازوں سے بالعموم زیادہ ہوتی ہیں.ایسی صورت
Page 16
میں حکم وہ دینا چاہیے تھا جس کا زیادہ نمازوں پر اطلاق ہو سکتا.نہ کہ ایسا حکم دیا جاتا جس پر عمل کرنے کا امکان سفر کی حالت میں بہت ہی کم ہوتا ہے مثلاً ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص شہر سے دس بجے صبح نکلے یا عصر اور مغرب کے درمیان نکلے یا آدھی رات کے وقت نکلے اور یہ سارے کے سارے اوقات ایسے ہیں جن میں نماز کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا.ان حالات میں وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا حکم بے معنی بن جاتا ہے.کیونکہ کسی شہر سے نکلتے وقت شاذ ہی نماز کا موقعہ ہوتا ہے.بالعموم یا تو انسان اس وقت نماز ادا کر چکا ہوتا ہے یا اگر ادا کرنی ہوتی ہے تو کچھ دیر کے بعد بھی وہ نماز پڑھ سکتاہے.بہر حال خروج کے ساتھ نماز کا تعلق نہیں.پھر ان معنوں کو اس صورت میں بھی درست تسلیم کیا جا سکتا تھا جب کوئی نماز خروج کے وقت سے بھی خاص طور پر تعلق رکھتی لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی نماز خروج کے وقت سے تعلق نہیں رکھتی ایسی صورت میں اس آیت کو بارادہ سفر گھر سے نکلنے پر چسپاں کرنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا.مزید دلیل اس بات کی کہ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ سے مراد نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا نہیں یہ ہے کہ سفر کی حالت میں تو بعض دفعہ جہت کا سوال بھی اُڑ جاتا ہے اور جدھر منہ ہو اُدھر ہی نماز جائز ہوجاتی ہے.مثلاً جب انسان سواری سے اُتر نہ سکے توقرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہی ثابت ہے کہ اس وقت اس کا جدھر منہ ہو جائے اُدھر ہی نماز جائز ہے.چاہے قبلہ کی طرف منہ ہو یا کسی اور طرف اس وقت جہت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا.مشرق مغرب شمال جنوب سب ایک جیسے ہوتے ہیں صرف قلبی توجہ خانہ کعبہ کی طرف ہونی ضروری ہے (البقرة:۱۱۶ و مسلم کتاب صلٰوة المسافرین باب جواز صلوٰۃ النافلۃ علی الدبۃ فی السفر حیث توجّھت ).آجکل جب انسان ریل گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جہت کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی کیونکہ گاڑی کبھی شمال کی طرف کبھی جنوب کی طرف کبھی مشرق کی طرف اور کبھی مغرب کی طرف مڑتی اور چکر کھاتی رہتی ہے.لیکن اس کے باوجود جو شخص اس میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا.اگر مفسرین کے معنوں کو درست سمجھا جائے تو اس حکم پر نہ سوار عمل کر سکتا ہے اور نہ ریل گاڑی پر بیٹھنے والا عمل کر سکتا ہے.پس جب خروج میں جہت کی تخصیص بھی قائم نہیں رہتی تو پھر اس آیت سے یہ مراد لینا کہ جہاں کہیں سے بھی تم نکلو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو.کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر یہ معنے اس لئے بھی درست نہیں کہ اس آیت کے لفظی معنے یہ بنتے ہیں کہ تم جہاں سے بھی نکلو اپنے منہ مسجد حرام کی طرف کر لو.یا جہاں سے بھی تُو نکلے تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے.اب یہ تو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ چلتے وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی بلکہ نماز ٹھہر کر ہی پڑھی جا سکتی ہے ہاں اگر اس آیت کے یہ الفاظ ہوتے کہ
Page 17
حَیْثُ مَاکُنْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ توجہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرلے.تب تو یہ معنے صحیح ہو سکتے تھے لیکن یہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی اے محمد رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ ٖ وسلم )یا اے مسلمانو! جہاں سے بھی تم نکلو تم اپنے منہ مسجد حرام کی طرف کر لو.اب یہ صاف بات ہے کہ نماز نکلتے وقت نہیں پڑھی جاتی بلکہ کسی جگہ ہوتے ہوئے نماز پڑھی جاتی ہے.پس معلوم ہوا کہ یہاں نماز پڑھنے کے معنے کرنا کسی صورت میں بھی درست نہیں.مفسرین کہتے ہیں کہ اگر نماز اور خروج کا کوئی تعلق تسلیم نہ کیا جائے تو پھر تکرار لازم آتا ہے حالانکہ یہ بھی غلط ہے.انہیں قرآن مجید میں تکرار صرف اس لئے نظر آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے صحیح مطالب اور مضامین کے باہمی ربط کو نہیں سمجھ سکے.انہیں جہاں بھی کوئی اعتراض نظر آتاہے فوراً ناسخ و منسوخ کی بحث شروع کر دیتے ہیں اور ایک آیت کو ناسخ اور دوسری کو منسوخ قرار دےکر اعتراض سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں.حالانکہ قرآن کریم کے جو حقائق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کو بتائے ہیں اگر ان کو مدِّنظر رکھا جائے تو نہ قرآن کریم میں کوئی تکرار نظر آسکتا ہے اور نہ کسی آیت کو منسوخ قرار دینا پڑتا ہے.اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا اس وقت دشمنانِ اسلام کو یہ اعتراض کرنے کا موقعہ ملا کہ جب آپ دُعائے ابراہیمی کے موعود تھے اور خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا تو آپ کو مکہ سے کیوں نکال دیا گیا.جب آپ کو مکہ سے نکال دیا گیا ہے تو آپ دُعائے ابراہیمی کے کس طرح مصداق ہو سکتے ہیں؟ اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِالْحَرَامِ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تمہارا مکہ سے یہ نکلنا عارضی ہے ہم تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ تمہیں یہ موقعہ دیں گے اور تم مکہ پر قابض ہو جائوگے.لیکن جہاںاللہ تعالیٰ کے مومن بندوں سے یہ وعدے ہوتے ہیں وہاں وہ ان سے یہ بھی اُمید کرتا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کریںگے یہ نہیں کہ خدا اُن سے وعدہ کرے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور وہ اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں اور یہ سمجھ لیں کہ جب خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ اُسے خود پورا کرے.ہمیں اُس کے پورا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اُسے کنعان کا ملک دیا جائے گا.حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر چل پڑے.جب وہ ملک سامنے آگیا تو آپ نے اپنی قوم سے کہا.جائو اور لڑائی کر کے اس ملک پر قبضہ کر لو.حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے غلطی سے یہ خیال کر لیا کہ خدا تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دینے کا وعدہ کیاہے اس لئے وہ خود ہی اس وعدے کو پورا کرے گا اور یہ ملک ہمارے قبضہ میں دے دےگا.ہم نے اگر اس ملک کو فتح کیا تو پھر وعدے کا کیا فائدہ ہوا.
Page 18
وعدہ تو خدا نے کیا ہے اس لئے وہ اسے خود پورا کرے.ہمیں اس کے لئے کسی قسم کی کوشش کی ضرورت نہیں.چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیاکہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (المائدة :۲۵ و خروج باب ۳ آیت ۸ تا ۱۷) اے موسیٰ! تُو ہم سے کہا کرتا تھا کہ یہ ملک خدا تعالیٰ تمہیں دے دےگا.اب تمام ذمہ داری تجھ پر ہے یا تیرے خدا پر.ہم نے اگر ملک فتح کیا تو پھر تیرے اور تیرےخدا کے وعدوں کا کیا فائدہ؟ چونکہُ تو ہمیں بتایا کرتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ ملک ہمیں ضرور ملے گا اس لئے اب ُتو اور تیرا رب دونو جاکر لڑو.ہم یہیں بیٹھیں گے.جب تم ملک فتح کر کے ہمیں دے دو گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے.اب بظاہر ان کا کہنا درست معلوم ہوتا ہے اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں تمہیں فلاں چیز دوںگا.اور وہ اس سے آکر وہ چیز مانگے اور وہ آگے سے کہہ دے کہ جائوبازار سے خرید لو.تو سارے لوگ یہی کہیں گے کہ اگر اُس نے وہ چیز بازار سے ہی خریدنی تھی تو پھر اس کے ساتھ وعدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پس بظاہر یہ بات معقول نظر آتی ہے لیکن الٰہی سلسلوں میں یہ اوّل درجہ کی غیر معقول بات ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تعریف نہیں کی.اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم یہ ملک لے کر تمہیں دیں.بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ہماری ہتک کی ہے اس لئے تمہیں اس ملک سے محروم کیا جاتا ہے.جائو چالیس سال تک جنگلوں میں بھٹکتے پھرو.تم اس ملک کے وارث نہیں بن سکتے.تمہاری نئی نسل اس ملک کی وارث ہوگی(المائدة :۲۷ و گنتی باب ۱۴ آیت ۳۳).کیونکہ تم نے ہماری ہتک کی ہے.تو دیکھو یہ چیز انسانی لحاظ سے تو درست اور معقول کہلاسکتی ہے لیکن الہٰی سلسلہ کے لحاظ سے نہایت ہی غیرمعقول ہے اور انسان کو عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی انسان وعدہ کرتا ہے تو اُسے تغیرات سماوی اور تغیرات ارضی پر اختیار نہیں ہوتا.اس لئے جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو ایسی چیز کا کرتا ہے جو اس کے اختیار میں ہوتی ہے.لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہو گا.اس کا یہ مطلب ہو گا کہ اگرچہ اُس چیز کا حصول تمہارے لئے ناممکن ہے مگر یہ تمہیں ہماری مدد سے حاصل ہو جائے گی.وہ قوم جو فرعون کی سینکڑوں سال تک غلام رہی اس کے لئے اینٹیں بناتی رہی لکڑیاں کاٹتی رہی اور ذلیل سے ذلیل کام کرتی رہی وہ اتنے بڑے عظیم الشان ملک پر جس پر عاد قوم حکمران تھی کیسے قبضہ کر سکتی تھی؟ اُسے یہ ملک مل جاناآسان نہیں تھا.لیکن خدا نے کہا کہ گو یہ ملک حاصل کرنا تمہیں ناممکن نظر آتا ہے لیکن ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ملک تمہیںدیں گے اور تم یہ ملک ہماری مدد سے حاصل کر لو گے.پس خدا تعالیٰ کے وعدے کے یہ معنے نہیں ہوا کرتے کہ چونکہ اس نے وعدہ کر دیا ہے اس لئے بندے کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں.بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم اس چیز کو حاصل کرنے کے
Page 19
لئے تدبیر اختیار کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم کامیاب ہو جائو گے.گویا اللہ تعالیٰ کے وعدے اَور رنگ کے ہوتے ہیں اور بندے کے وعدے اور رنگ کے ہوتے ہیں.خدا تعالیٰ کے وہ وعدے جن میں تدبیر شامل ہوتی ہے بندے کو ان میں دخل دینا پڑتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے.اگر بندہ ان میں دخل نہیں دےگا اور ان کو پورا کرنےکی کوشش نہیں کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہو گا.لیکن بندے کے وعدہ میں یہ نہیںہوتا.بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے لئے خدا تعالیٰ کی تقدیر بدل دوں گا.کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتی.اگر وہ ایسا کہے گا تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم تقدیر کو بدلنے والے کون ہو؟ لیکن خدا تعالیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری مدد کروںگا اور اپنی تقدیر کو بدل دوں گا.کیونکہ تقدیر ایسی چیز ہے جو اس کے قبضہ میں ہے اور وہ جب چاہے اُسے بدل سکتا ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کا وعدہ دیا گیا تو ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ اے مسلمانو! تم موسیٰ ؑ کی قوم کی طرح یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا نے مکہ دے دینے کا وعدہ کیا ہے وہ خود اُسے پورا کرےگا.ہمیں اس کے لئے تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تمہیں بھی اس کے پورا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی.خدائی وعدے کے یہ معنے ہیں کہ تم کمزور ہو اگر تم کمزور نہ ہوتے تو تم مکہ کو چھوڑ کر کیوں آتے مکہ کو چھوڑنے کے معنے ہی یہ تھے کہ تم کمزور ہو اور تمہارا دشمن مضبوط اور طاقتور ہے لیکن خدا تعالیٰ تمہیںطاقت دےگا اور تم دشمن سے مکہ چھین لو گے پس وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے معنے یہ ہوئے کہ تم جہاں سے بھی نکلویا جس جگہ سے بھی نکلو تمہار ا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مکہ فتح کرنا ہے.پھرخروج کے معنے جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے لشکر کشی کے بھی ہوتے ہیں.اس صورت میں آیت کے یہ معنے ہوںگے کہ تم جہاں بھی لشکر کشی کرو کسی جگہ بھی لڑائی کےلئے جاؤ.چاہے تم مشرق کی طرف نکلویا جنوب کی طرف نکلو.مغرب کی طرف نکلو یا شمال کی طرف نکلو تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ خروج فتح مکہ کی بنیاد قائم کرنےوالا ہو.مثلاً تم اگر جنوب کی طرف دشمن پر حملہ کرنا چاہو لیکن تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس ملک کے مغرب کی طرف اس کے دوست موجود ہیں اور اُن کے متعلق یہ شبہ ہے کہ وہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کردیں اور تم پہلے مغرب کی طرف حملہ کرکے اُن کو صاف کر لو تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ یہ مغرب کی طرف حملہ اصل میں جنوب کے حملہ کا پیش خیمہ ہے.اسی طرح اگر اس قوم کے ساتھی شمال میں بستے ہوں اور پہلے تم اُن پر حملہ کرو تو تمہارا یہ حملہ اصل میں جنوب پر ہی ہو گا کیونکہ اصل مقصد تمہارا جنوب کے دشمن پر حملہ کرنا ہوگا.اسی اصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہےکہ اے مسلمانو! تم کسی قوم کسی ملک اور کسی علاقے پر چڑھائی کرو تمہارا رخ مکہ کی طرف ہونا
Page 20
چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں پر فتح کرنا چاہتا ہے.چنانچہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں یہ رنگ نمایاں طورپر پایا جاتا ہے اور آپ کی سب لڑائیوں کا مقصد اعلیٰ فتح مکہ ہی تھا.جس جنگ میں آپ یہ مقصد فوت ہوتا دیکھتے یا جس قوم کے متعلق آپ محسوس فرماتے کہ اس سے جنگ کرنے کے نتیجہ میں فتح مکہ میں تاخیر ہو جائے گی.وہاں باوجود اُکسائے جانے کے آپ خاموشی اور چشم پوشی اختیار فرماتے.چنانچہ کئی قومیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کےلئے اُٹھیں اور انہوں نے چھیڑ چھاڑ بھی کی مگر آپ ہمیشہ اغماض سے کام لیتے رہے لیکن جب کوئی ایسی قوم کھڑی ہوئی جس کو شکست دینے سے فتح مکہ قریب ہو سکتی تھی تو اُس کے ساتھ آپؐ نے ضرور جنگ کی.اگر تمام اسلامی غزوات پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ اپنے اندر ایک حکیمانہ رنگ رکھتی تھیں بالخصوص فتح مکہ سے پہلے جس قدر جنگیں ہوئیں.اُن سب کا مقصد صرف یہی تھا کہ فتح مکہ کا راستہ صاف کیا جائے.اگر اس آیت کے یہ معنے ہوتے کہ تم جہاں سے بھی نکلو قبلہ کی طرف اپنا منہ کرو تو جیسا کہ بتایا جا چکا ہے مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ کے الفاظ اس آیت میں نہ ہوتے بلکہ ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ ہوتے کہ تم جہاں کہیں ہو قبلہ کی طرف اپنا منہ رکھو.قبلہ کی طرف منہ کرنے کے لئے جہاں کہیں کے الفاظ ہونے چاہیے تھے.نہ یہ کہ تم جہاں سے بھی نکلو قبلہ کی طرف اپنا منہ پھیر دو.کیونکہ لوگ کہیں سے نکلتے وقت نمازیں نہیں پڑھا کرتے.نکلتے وقت تو لوگ چلا کرتے ہیں.پس اس آیت کا نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.بلکہ اس آیت کا صرف یہ مطلب ہے کہ تم جہاں سے بھی نکلو.چاہے تم اس مقام سے نکلو جس کا منہ مشرق کی طرف ہو.چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ مغرب کی طرف ہو.چاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ شمال کی طرف ہوچاہے اس مقام سے نکلو جس کا منہ جنوب کی طرف ہو بہرحال تمہارا منہ مکہ کی طرف ہونا چاہیے.یعنی تمہاری توجہ اور تمہارا خیال اور تمہارا ذہن صرف اسی بات کی طرف رہنا چاہیے کہ تم نے مکہ فتح کرنا ہے.اور وہاں اسلام کو قائم کر کے سارے عرب کو زیر اثر لانا ہے.وُجُوْہٌ کے معنے توجہات کے بھی ہوتے ہیں (المفردات) پس اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ تم نے خانہ کعبہ کو فتح کرکے اُسے اسلام کا مرکز بنانا ہے کیونکہ جب تک مکہ میں اسلام پھیل نہیں جاتا جب تک مکہ مسلمانوں کے ماتحت نہیں آجاتا اس وقت تک باقی تمام عرب مسلمان نہیں ہو سکتا.یہ پروگرام تھا جو مسلمانوں کا مقرر کیا گیا.اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ پروگرام ان کی طاقت سے بہت بالا تھا.بے شک عرب کی حکومت کوئی منظم حکومت نہ تھی مگر وہ طوائف الملوکی بھی نہیں تھی.مختلف بادشاہ اس کے ساتھ تعلق رکھتے اور معاہدات وغیرہ کرتے تھے.اسی طرح مکہ گو پوری طرح منظم نہ ہو مگر بہر حال وہ ایک ایسے
Page 21
ملک کا دارالحکومت تھا جس کی آبادی پندرہ بیس لاکھ تھی.اردگرد کے تمام قبائل کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی تھیں اور وہ اس کے فیصلوں اور حکموں کو واجب الاطاعت سمجھتے تھے.پھر اس زمانہ کے لحاظ سے وہ ایک بہت بڑا شہر تھا.پندرہ سولہ ہزار اس کی آبادی تھی اور نہ صرف اس کی تمام کی تمام آبادی بلکہ ملک بھر کے پندرہ بیس لاکھ آدمی سب کے سب سپاہی تھے.فنون جنگ میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے.جنگجو بہادر اور لڑاکے تھے اور مسلمانوں کے لئے ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا.جس وقت یہ آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اُس وقت مسلمانوں میں صرف چار پانچ سو سپاہی تھے.زیادہ سے زیادہ ہزار سمجھ لو اور عورتوں اور بچوں وغیرہ کو ملا کر ان کی کل تعداد گیارہ بارہ ہزار ہوگی.اس سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی اور ان کی جنگی طاقت تو بہر حال ناقابلِ ذکر تھی.مگر ایسی حالت میں جبکہ مسلمان سخت کمزور تھے.جب اُن کی تعداد کفار کے مقابلے میں کوئی نسبت ہی نہیں رکھتی تھی.جب ان کے پاس لڑائی کا کوئی سامان نہ تھا.اور جب اُن کی جنگی طاقت کفار کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی تھی اللہ تعالیٰ تمام کفار کو چیلنج دیتا ہے کہ یہ مسلمان گو تمہیں تھوڑے دکھائی دیتے ہیں.تمہیں کمزور اور ناطاقت نظر آتے ہیں مگر یہی مسلمان ایک دن تمہارے ملک کو فتح کریںگے.تمہارے دارالحکومت پر قابض ہوں گے اور وہاں ان کو اس قدر غلبہ میسر آجائے گا کہ یہ اسلام کے احکام کو وہاں جاری کریںگے اور کفر کو عرب کی سرزمین سے بالکل مٹا دیں گے.یہ دعویٰ مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے ایک مجنونانہ دعویٰ تھا اور پھر یہ دعویٰ ایسا تھا جو کسی خاص علاقہ سے مخصوص نہیں تھا.بلکہ اس دعویٰ کا اثر وسیع سے وسیع تر تھا کیونکہ نہ صرف اس میں مکہ کو فتح کرنے کی پیشگوئی کی گئی تھی.نہ صرف عرب پر غالب آجانے کا اعلان کیا گیا تھا بلکہ عیسائیت کو بھی چیلنج دیا گیا تھا.یہودیت کو بھی چیلنج دیا گیا تھا.مجوسیت کو بھی چیلنج دیا گیا تھا.اور بڑے زور سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان تمام مذاہب کو شکست دے کر اسلام ساری دنیا پر غالب آجائے گا.یہ دعویٰ ایک مجنونانہ دعویٰ تھا.اسی وجہ سے کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو پاگل کہا کرتے تھے اور صحابہؓ کو بھی وہ پاگل سمجھتے تھے کیونکہ وہ ایک ایسا دعویٰ کر رہے تھے جس کے پورا ہونے کے اس مادی دنیا میں انہیں کوئی اسباب نظر نہیں آتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک غیر معمولی کاموں کے لئے ہر انسان کے اندر وہ حالت پیدا نہ ہو جائے جسے بعض حالتوں میں طب مانومینیا کہتی ہے.جب تک وہ اَور تمام مقاصد کو بھول نہ جائے جب تک اس کے اندر ہر وقت ایک خلش اور بے تابی نہ پائی جائے اور جب تک غیر معمولی کاموں کے لئے اس کے اندر جنون کا سا رنگ پیدا نہ ہو جائے اُس وقت تک ان کاموں میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی.اسی کی طرف قرآن کریم نے اس آیت میں توجہ دلائی ہے کہ تم باقی تمام مقاصد کو بھول جائو اور
Page 22
صرف اس مقصد کو اپنے سامنے رکھو کہ ہم نے مکہ کو اسلام کے لئے فتح کرنا ہے.جب تک یہ مرکز اور یہ قلعہ تمہیں حاصل نہیں ہو گا سارے عرب اور پھر ساری دنیا پر تمہیں غلبہ میسر نہیں آسکے گا.یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تم جس جگہ سے بھی نکلو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف رکھو.یہ کیوں نہیں کہا کہ تم جس طرف بھی حملہ کرو اپنی توجہ مسجد حرام کی طرف رکھو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خروج کے وقت ہی یہ فیصلہ کیاجاتا ہے کہ ہمارا اس حملہ سے کیامقصد ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ انسان لڑائی تو پہلے شروع کر دے او ر اس کا مقصد بعد میں سوچے.پس چونکہ یہاں فتح مکہ کے مقصد کو سامنے رکھنے کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا اس لئے فرمایا کہ تم نکلتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ ہماری اس جنگ کا اثر فتح مکہ پر کیا پڑے گا؟ اگر وہ جنگ فتح مکہ میں ممدنہ ہو تو اسے چھوڑ دو.مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام اپنے پیروئوں کو جارحانہ جنگ کی اجازت دیتا ہے.کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان آیات کے نزول سے پہلے ہی کفار سے جنگیں شروع ہو چکی تھیں.یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مِنْ حِیْثُ خَرَجْتَ میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایاگیا ہے.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس رنگ میں فتح مکہ کی ضرورت باقی نہیں رہنی تھی کیونکہ آپؐ کے بعد مکہ پر کوئی حملہ نہیں ہونا تھا بلکہ اس نے کامل طور پر مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہنا تھا.گویا اس میں آئندہ کے لئے یہ پیشگوئی کر دی کہ مکہ مکرمہ کی دوبارہ جسمانی فتح نہیں ہو گی کیونکہ مکہ کی عظمت قائم کرنے والی ایک فعال جماعت پیدا کر دی جائے گی.اور وہ ہمیشہ مسلمانوں ہی کے قبضہ میں رہے گا.وَ اِنَّہٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ.فرماتا ہے کہ یہ بات تو تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی ہے.ان آیات کے نزول کا زمانہ ہجرت کے سولہ ماہ بعد کا ہے.اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات ابھی کامل طور پر دُور نہیں ہوئی تھیں اور ابھی کامل طور پر آپ کا رعب اور دبدبہ اور حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی.ایسی صورت میں بظاہر یہ ایک ہنسی کی بات تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیں گے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باتیں بنانے والے اور مخالفین وغیرہ بے شک استہزاء سے کام لیں.یہ بات تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہے گی اور ان کو بھی توجہ دلائی ہے کہ تم لوگ اس کو ناممکن خیال کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس پیشگوئی کو پورا کر کے دکھا دےگا.پھر یہ فقرہ اس لئے بھی کہا گیا ہے کہ انسان جنگ سے ڈرتا اور گھبراتا ہے اُسے یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ معلوم نہیں فتح نصیب ہو گی یا شکست.لیکن جہت مخصوصہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا انسان کی ہمت کو بڑھا دیتا ہے.چنانچہ جب بھی کسی کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی یہ آیت اس کے لئے تسلّی کا موجب ہو جاتی کہ
Page 23
اِنَّہٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ یہ بات تمہارے رب کی طرف سے ہو کر رہنے والی ہے.اور وہ اس کام میں تمہارا حامی اور مددگار ہو گا.اسی طرح رَبِّکَکہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر کام کے کچھ محرک ہوا کرتے ہیں اور بہترین محرک کسی کام کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میرا محسن مجھ سے یہ خواہش رکھتا ہے.ایسی حالت میں وہ بسا اوقات اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے.تمہیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا رب جو تمہارا محسن ہے اُس کی یہ خواہش ہے کہ تم مکہ کو فتح کرو.پس گویہ بات ایک دن پوری ہو کررہے گی مگر محسن کے احسان کا بدلہ اتارنا بھی تمہارا کام ہے اس لئے تمہیں اس کے متعلق اپنے سرد ھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے اور اس عظیم الشان مقصد کے حصول کے لئے کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے.وَمَا اللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.اس کے یہ معنے نہیں کہ وہ تمہیں سزا دےگا بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو دیکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسلام اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتاجب تک مکہ فتح نہ ہو جائے اس لئے تم اپنی کوشش اور جدوجہد کو جاری رکھو اور فتح مکہ کو کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو.خدا تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں ہونے دےگا.اس میں مسلمانوں کو قربانیوں کے لئے اُبھارا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو دیکھتا ہے مگر تمہارے انعام اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم مکہ فتح نہ کر لو.سو کوشش کرو کہ مکہ جلد فتح ہو جائے.اس میں جتنی دیر ہو گی اتنی ہی تمہاری ترقی پیچھے پڑ جائے گی.وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ١ؕ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ.یورپین مستشرق کہتے ہیں کہ اس جگہ قرآنی آیات میں تکرارپایا جاتاہے.جو فصاحت کے خلاف ہے.(Introduction to the Quran , Richard Bell).جب اس سے پہلے غیر مبہم الفاظ میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تواس کے معاً بعد پھر انہی الفاظ کا کیوں تکرار کیا گیاہے؟ اس اعتراض کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ مخالفینِ اسلام کی اتنی بات تو درست ہے کہ ان دونوں آیات کے معنوں میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ بات درست نہیں کہ ان دونوںکو ایک ہی غرض کے ماتحت بیان کیا گیا ہے بلکہ ان دونوں کے بیان کرنے کی اغراض مختلف ہیں.اگر دونوں جگہ ایک ہی غرض کام کر رہی ہوتی تو پھر تو بے شک تکرار کا اعتراض درست ہوتا لیکن جب کسی نئی غرض کے لئے پہلے کلام کو دہرایا جائے تو وہ حُسنِ کلام کے منافی نہیں ہوتا.صرف وہ تکرار قابلِ اعتراض ہوتا ہے جو بغیر غرض اور فائدہ کے ہو لیکن اگر ایک حکم کو بیان کیا جائے اور پھر اس کے دُہرانے کی کوئی نئی غرض پیدا ہو جائے تو اُسے تکرار نہیں کہا جاتا.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ہم بعض دفعہ مجلس میں کہتے ہیں
Page 24
’’بیٹھ جائو‘‘ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ’’بیٹھ جائو‘‘ پھر کچھ وقفہ کے بعد کہتے ہیں ’’بیٹھ جائو‘‘ اب بظاہر ان الفاظ میں تکرار نظر آتا ہے لیکن جب ہم پہلی مرتبہ یہ الفاظ کہتے ہیں تو ہمارے مخاطب وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت کھڑے ہوتے ہیں.لیکن جب دوبارہ یہی الفاظ کہتے ہیں تو وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو ابھی تک نہیں بیٹھے ہوتے.اور جب ہم تیسری دفعہ کہتے ہیں تو وہ پانچ دس لوگ مخاطب ہوتے ہیں جو ابھی تک کھڑے ہوتے ہیں.اب یہاں ایک جملے کا کئی دفعہ بولنا غیرفصیح نہیں اور نہ ہی اسے تکرار کہاجاتا ہے بلکہ ہر فقرہ اپنی ذات میں الگ الگ غرض کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح اس آیت میں بھی تکرار نہیں کیونکہ یہاں خدا تعالیٰ کا دوسری دفعہ وہی فقرہ لانا اپنے اندر ایک نئی حکمت رکھتا ہے.چنانچہ پہلی آیت میں تو صرف یہ بتایا تھا کہ تمہاری لڑائیوں کا نقطہ مرکزی مکہ کی فتح ہونا چاہیے اور دوسری آیت میں فتح مکہ اور تحویل قبلہ کے بارہ میں دونوں حکموں کو جمع کر کے ان کی وجہ بتائی ہے اور وہ لِئَلَّا یَکُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّۃٌہے.اورحجت سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ ہو ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو غالب کر دینے والی ہو.پس یہ تکرار نہیں بلکہ فقرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ یہ دونوں باتیں دہرائی نہ جائیں.یعنی مکہ فتح نہ ہوا تب بھی تم پر لوگوں کی حجت ہو گی اور اگر ادھر منہ نہ کیا تب بھی حجت ہو گی.پس اس کا خیال رکھنا ضروری ہے اگر تم نے مکہ فتح نہ کیا تو تمہاری ترقی کے راستہ میں کئی قسم کی روکیں پیدا ہو جائیںگی.اور اسلام پر دشمنوں کے اعتراضات کا دروازہ کھلا رہےگا.غرض دونوں آیات الگ الگ مقاصد رکھتی ہیں اور دوسری جگہ اس مضمون کو جسے پہلی آیت میں اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا وسیع کردیا گیا ہے.اور ان فوائد کو واضح کیا گیا ہے جو فتح مکہ اور تحویل ِ قبلہ کے ساتھ وابستہ تھے.اسی طرح دوسری آیت میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اے مسلمانو! تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا فرض ہے کہ تم خانہ کعبہ کی حفاظت کرو.اور اُسے دشمنوں کے حملوں سے بچائو.یہ مضمون پہلی آیت میں نہیں تھا پس گو اس آیت میں بھی فتح مکہ کا ہی ذکر ہے مگر پھر بھی اسے تکرار نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں نئے اسلوب اور نئے انداز سے فتح مکہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اس کے فوائد بیان کئے گئے ہیں.پھر ایک اور نقطۂ نگاہ بھی تکرار کے اعتراض کو باطل ثابت کرتا ہے اور وہ یہ کہ پہلی آیت اُن اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے ہے جو اخلاقی اور روحانی لحاظ سے دوسرے لوگوں سے بہت بڑھے ہوئے اوراپنے اندر خاص فوقیت رکھتے ہیں یا بالفاظ دیگروہ آیت ایسے لوگوں کے لئے ہے جو اخلاق اور رُوحانیت کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مدغم ہیں.اور کامل طور پر آپ کے ظل کہلا سکتے ہیں.ایسے وجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جُدا نہیں
Page 25
بلکہ آپؐ میں ہی شامل ہوتے ہیں.اس لئے ان کا ذکر آپؐ سے علیحدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی.یہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے متعلق یہ علم تھا کہ ان کے لئے اِنَّہٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَکہہ دینا ہی کافی محرک ہوسکتا ہے چنانچہ اگر غور سے کام لیا جائے تو دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ دکھائی دیتے ہیں ایک تو وہ جو اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو ادنیٰ درجہ کے ہوتے ہیں.اعلیٰ درجہ کے انسانوں کے لئے باریک باتیں ہی کافی محرک ہو جاتی ہیں لیکن ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے قریب کا محرک کام کرتا ہے مثلاً اعلیٰ درجہ کے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو و ہ اس بات کو اپنے دل کے کسی گوشہ میں بھی نہیں لاتے کہ ان کو نماز کے بدلہ میں کیا ملے گا.وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز خدا تعالیٰ کے احسانات کے شکریہ کے طور پر ہے کسی جزا کے لئے نہیں.وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر پہلے ہی کیا کم احسانات ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر اس سے بدلہ کی خواہش رکھیں.وہ لوگ اسی کو بہت بڑا احسان اور اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے لیکن اس کے مقابل پر ادنیٰ درجہ کے لوگ اگر چند دن بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جھٹ کہنے لگ جاتے ہیں کہ نمازوں میں کیا رکھا ہے ہم نے تو نمازیں پڑھ پڑھ کر دیکھ لیا ہے کہ ان میں کچھ بھی نہیں.ایسے لوگ سودے کے طور پر نمازیں پڑھتے ہیں یہ لوگ بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں محبت رکھی.وہ اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے جاری کر دیئے تھے اور وہ اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کے باپ کے دل میں رافت پیدا کر دی تھی اور اسے روزی کمانے کی توفیق دی وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دینی و دنیوی ترقی کے لئے انہیں ناک کان آنکھیں دل اور دماغ وغیرہ عطا فرمائے ہیں.وہ اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی زندگی کے قیام کے لئے سورج چاند ستارے آگ ہوا پانی زمین اور غذائیں وغیرہ پیدا کی ہیں.وہ اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ سب انعامات کسی عمل کے نتیجہ میں نہیں ملے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے نتیجہ میں ملے ہیں غرض ایک طرف تو بعض لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے اور دوسری طرف ایسے انسان بھی ہیں جو اپنے دل میں بدلے کا خیال تک نہیں لاتے.وہ سوالی بن کر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگ تو لیتے ہیں مگر اپنے عمل کے بدلہ میں انعام کے طالب نہیں ہوتے.یہ لوگ نماز روزہ زکوٰۃ حج اور غریب پروری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے انعام کے طالب نہیں ہوتے بلکہ اسی کو وہ لوگ انعام سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکریہ ادا کرنے کا موقعہ اور توفیق عطا فرمائی.یہ لوگ کنگال ہو کر بھی اپنے عمل کے بدلہ میں کسی انعام کے طالب نہیں ہوتے وہ
Page 26
اللہ تعالیٰ سے مانگنا پسند کرتے ہیں مگر عمل کے بدلہ میں انعام طلب نہیں کرتے.میں نے کئی دفعہ ایک بزرگ کا واقعہ سنایا ہے جو متواتر بیس سال ایک ہی دعا کرتے رہے اور ان کی دعا قبول نہ ہوئی اس عرصہ میں ان کا ایک مرید بھی آگیا.وہ بزرگ رات کو اُٹھ کر دُعا مانگ رہے تھے کہ انہیں الہام ہوا کہ تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہو گی.یہ الہام ان کے مرید نے بھی سن لیا مگر وہ شرم کے مارے چپ رہا اور اس نے زبان سے کچھ نہ کہا دوسری رات پھر اس بزرگ نے دعا کی تو پھر الہام ہوا کہ تمہاری یہ دُعا قبول نہیں ہو گی اور ساتھ ہی مرید کو بھی اس کا پتہ لگ گیا.مگر وہ پھر بھی شرم کے مارے چپ رہا تیسری رات پھر وہ بزرگ مصلّے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ الہام ہوا تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہو گی.اور مرید نے بھی یہ آواز سن لی.وہ خاموش نہ رہ سکا اور اس نے کہا کہ ایک دفعہ دعا قبول نہ ہو یا دو فعہ قبول نہ ہو تو کوئی بات نہیں مگر آپ کو تو کئی بار کہا گیا کہ یہ دُعا قبول نہیں ہو سکتی مگر پھر بھی آپ مانگتے چلے جاتے ہیں.اُس بزرگ نے کہا کہ تم تو ابھی سے تھک گئے ہو میں تو یہ دعا بیس سال سے متواتر کر رہا ہوں اور بیس سال سے ہی مجھے یہ جواب مل رہا ہے.لیکن پھر بھی میں مانگتا چلا جاتاہوں لیکن تم تین دن سے ہی یہ آواز سن کر کہتے ہو کہ بس کرو.میرا کام اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام ماننا اور قبول کرنا ہے میں اپنا کام کر تا جائوں گا اللہ تعالیٰ اپنا کرے گا.وہ مانے یا نہ مانے اس کا اپنا اختیار ہے.پس اعلیٰ درجہ کے لوگ گھبراتے نہیں وہ اعمال بجا لاتے ہیں مگر اس کے بدلے میں انعام کے طالب نہیں ہوتے.ایسے لوگوں کے لئے اِنَّہٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ کہنا ہی کافی تھا.یعنی تمہارے رب کی یہ خواہش ہے کہ تم ایسا کرو.لیکن دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اعلیٰ ایمان والے نہیں یہ لوگ چونکہ کام کرنے سے پہلے یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا.اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کر دیا کہ فتح مکہ کے نتیجہ میں ان پر کیا کیا انعامات نازل ہوں گے چنانچہ فرمایا.لِئَلَّا یَکُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّۃٌ.یہ حکم تمہیں اس لئے دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ مل جائے.یعنی اگر تم مکہ فتح کرنے کے لئے نکلو گے تو سب سے پہلا انعام تم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو گا کہ آئندہ تم پر لوگ اعتراض نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی تمہارے خلاف کوئی دلیل قائم کر سکیں گے.دوسرا انعام جو ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے بیان کیا گیا ہے وہ وَلِاُ تِمَّ نِعْمَتِیْ ہے.یعنی اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت اور بادشاہت عطافرمادےگا.اس کا بیان کرنا صرف ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے ہی ہے.ورنہ اعلیٰ درجہ کے لوگ ان باتوں کی پروا نہیں کرتے کہ ان کو کچھ ملے گا بھی یا نہیں.تیسرا انعام لَعَلَّکُمْ تَھْتَدُوْنَ کے الفاظ میں بیان فرمایا کہ اس کی غرض یہ ہے کہ تم ہدایت پائو.ہدایت دراصل
Page 27
مقصود تک پہنچنے کو کہتے ہیں پس ان الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو مل جائو گے.پہلے تم میں سے خاوند اپنی بیوی سے بیوی اپنے خاوند سے.بیٹا اپنے باپ سے اور باپ اپنے بیٹے سے جُدا تھا.اب مکہ کی طرف نکلنے میں تمہارا یہ بھی فائدہ ہے کہ تم ان کو مل جائو گے.اور وہ سارا جھگڑا جس کے باعث تم ایک دوسرے سے جُدا تھے دُور ہو جائے گا.پس ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے جو کام کرنے سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے انعامات بیان فرمائے (۱)لِئَلَّا یَکُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّۃٌ(۲) وَلِاُ تِمَّ نِعْمَتِیْ عَلَیْکُمْ(۳) لَعَلَّکُمْ تَھْتَدُوْنَ پہلا انعام ذہنی ہے اس کے ذریعہ انسان کو دماغی طور پر اطمینان حاصل ہو جاتا ہے.دوسرا انعام مادی ہے یعنی حکومت اور بادشاہت تم کو مل جائے گی.تیسرا انعام دل کے اطمینان کے لئے ہے کہ جب تم رشتہ داروں کو مل جائو گے تو تم کو اطمینانِ قلب حاصل ہو جائے گا.غرض پہلا حکم اَور غرض سے ہے اور دوسرا اَور غرض سے.پہلے تو جنگ کا ذکر تھا اور اس کی غرض یہ بتائی تھی کہ اِنَّہٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّکَ یعنی خدا کا چونکہ وعدہ ہے اس لئے اپنے محبوب کے وعدہ کو پورا کرنے کے لئے تمہیں کوشش کرنی چاہیے.گویا ایک اعلیٰ غرض بتائی جو صرف کامل الایمان لوگوں کے سامنے ہوتی ہے مگر ساتھ ہی فرما دیا کہ جس طرح تمہارا اعلیٰ مقصد یہ ہو کہ ہمیں انعامات سے کیا تعلق ہے ہم نے تو اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا ہے.اسی طرح میرا اعلیٰ تعلق بھی تو یہ ہے کہ میں تمہارے اعمال سے غافل نہ رہوں اور کسی عمل کو ضائع نہ جانے دوں یعنی جب تم کوشش کرو گے تو میری غیرت بھی جوش میں آئے گی اور میں اعلیٰ سے اعلیٰ برکات تم پر نازل کروں گا اس کے بعد دوسری دفعہ اس حکم کو اُن لوگوں کے لئے دُہرایا ہے جو ایمان کے لحاظ سے اس اعلیٰ مقام پر فائز نہیں تھے جس پر پہلا گروہ قائم تھا اور بتایا کہ فتح مکہ کے نتیجہ میں یہ تین فائدے تمہیں حاصل ہوں گے اوّل دشمن کا اعتراض جاتا رہے گا.دوم فتح دنیوی حاصل ہو کر تمہیں امن میسر آجائے گا.سوم تمہارے وہ عزیز اور رشتہ دار جواب بوجہ اختلاف مذہب تم سے جدا ہیں وہ تمہارے ساتھ آملیں گے.گویا روحانی مادی اور قلبی تینوں قسم کے آرام تمہیں نصیب ہوجائیںگے.پس چونکہ اس جگہ پہلی غرض کی نسبت ادنیٰ فوائد مذکور تھے اور پہلی جماعت کی نسبت ایک کمزور جماعت کو شامل کرنا مقصود تھا اس لئے اس کو الگ بیان کیا.اور چونکہ یہی فوائد پہلی جماعت کو بھی ملنے والے تھے اس لئے اس کو بھی ساتھ شامل کر دیا.پس یہ تکرار نہیں بلکہ دوسری آیت میں ان کمزوروں کا ذکر کیا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل ظل نہ تھے اور پہلے حکم میں شامل نہ ہو سکتے تھے او رپھر ان کے لئے وہ فوائد بیان کئے جو ان کے شایانِ شان تھے اور ساتھ ہی پہلوں کو بھی شامل کر لیا کیونکہ ان کو بھی وہ چیزیں ملنے والی تھیں.اگر انہیں شامل نہ کیا جاتا تو یہ سوال
Page 28
پیدا ہوسکتا تھا کہ جب یہ انعامات ادنیٰ درجہ کے لوگوں کو ملیں گے تو کیا اعلیٰ درجہ کے لوگ ان انعامات سے محروم رہیں گے؟ اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹکڑہ میں ان کامل الایمان لوگوں کا ذکر کر دیا اور بتادیا کہ گو وہ انعامات کے لالچ میں کوئی کام نہیں کرتے مگر جہاں تک ان فوائد کا تعلق ہے جو فتح مکہ سے وابستہ ہیں وہ ان سے محروم نہیں رہیں گے بلکہ جس طرح دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گےاسی طرح وہ بھی فائدہ اُٹھائیں گے.یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ حَیْثُ مَاخَرَجْتُمْ نہیں بلکہ حَیْثُ مَا کُنْتُمْ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بعض کمزوراور معذور لوگ بھی تھے جن کی جسمانی کمزوریاں اُن کے نکلنے میں مانع تھیں جیسے لنگڑے یا اپاہج وغیرہ پس ان کو مدِّنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حَیْثُ مَاخَرَجْتُمْ کی بجائے حَیْثُ مَا کُنْتُمْ کے الفاظ استعمال فرما کر یہ ظاہر کیا کہ اس ثواب میں صرف وہی لوگ شریک نہیں ہوں گے جو خروج کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ وہ بیمار جو چارپائیوں سے ہل نہیں سکتے.وہ اپاہج جو چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ بیمار اور کمزور جو اپنی بیماری اور کمزوری جسم کی وجہ سے لڑائی کے ناقابل ہیں اگر وہ فتح مکہ کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے دل اس حسرت سے پُر ہیں کہ کاش اُن میں طاقت ہوتی اور وہ بھی جنگ میں شریک ہو سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا اور ان کو بھی ویسا ہی ثواب دیا جائے گا جیسے عملی طور پر جنگ میں حصہ لینے والوں کو دیا جاتاہے غرض کمزور اور معذور لوگوں کو جو صدمہ ہوتا ہے کہ ہم اس ثواب سے محروم رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صدمہ کو دور کرنے کے لئے وَحَیْثُ مَاکُنْتُمْکے الفاظ استعمال فرما دئے تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں.ایک اپاہج اور کمزور آدمی جنگ میں شامل نہیں ہو سکتا.اگر وہ رات دن دُعائیں کر سکتا ہے کہ یا اللہ! مسلمانوں کو فتح دے اور انہیں مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل فرما یا اگر اس کے پاس کوئی غیر مسلم آجاتا ہے اوروہ اُسے تبلیغ کر کے مسلمان بنا لیتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے عملی طور پر جنگ میں شامل ہونے والا.یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حَیْثُ مَا خَرَ جْتُمْ نہیں بلکہ حَیْثُ مَا کُنْتُمْ فرمایا ہے اور یا پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کو بھی شامل کر لیاہے جب جنگ نہ ہو.اور ہدایت دی ہے کہ جب جنگ کو نکلو تب بھی اور جب گھروں میں ہوتب بھی مکہ کی فتح کو اپنی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دو.اسی طرح ان الفاظ میں مسلمانوں کو اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ تم جہاں کہیں ہو تمہارا منہ ہمیشہ مکہ ہی کی طرف رہنا چاہیے.یعنی تمہیں ہمیشہ اپنے مرکز کی ترقی اور وہاں کے رہنے والوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور یہ امر مدِّنظر رکھنا چاہیے کہ اگر مکہ مکرمہ میں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اس کا سارے عالم اسلام پر اثر پڑے گا اور اگر مکہ کی ترقی ہوئی تو اس کا اثر بھی تمام عالمِ اسلام پر
Page 29
پڑے گا.کیونکہ لوگوں نے وہاں بار بار حج اور عمرہ کے لئے جانا ہے اور دنیا کے کناروں سے وہاں اکٹھا ہونا ہے.پس تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کوئی خرابی پیدا نہ ہو.اگر وہاں خرابی پیدا ہوئی تو لازماً ساری دنیا پر اس کا اثر پڑے گا.چنانچہ دیکھ لو اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق اب تک بعض مخالف یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے دعوے میں کس طرح سچا سمجھ لیں جبکہ مکہ کے علماء نے بھی آپؑ پر کفر کے فتوے لگائے.اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مکہ والوں کی اصلاح کی طرف توجہ رکھنا کس قدر ضروری ہے.بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیت اللہ کبھی غیر مسلموں کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا.مگر اس پر شیطانی حملے تو ہر وقت ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اسی طرح وہاں کے رہنے والوں میں بھی کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں.پس اس آیت میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اے مسلمانو! تم خواہ دنیا کے کسی گوشہ میں رہتے ہو تمہیں ہمیشہ مکہ کی طرف اپنی توجہ رکھنی چاہیے اور اس کی اصلاح اور ترقی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے.افسوس ہے کہ گذشتہ دور میں مسلمانوں نے اس اہم فرض کو نظر انداز کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود ان میں بھی کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئیں.میں جب اسلامی تاریخ کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت آتی ہے کہ مکہ اور مدینہ کی آبادی تو چند ہزار یا ایک لاکھ کے ارد گرد گھومتی رہی.مگر بغداد، دمشق اور قاہرہ کی آبادی اور ایران اور ہندوستان کے اسلامی شہروں کی آبادیاں بیس بیس لاکھ تک پہنچ گئیں.میں سمجھتا ہوںاسلام کے تنزل میں اس بات کا بھی بڑا دخل تھا کہ مسلمانوں میں اپنے مذہبی مرکز میں بسنے کی خواہش اتنی نہ رہی جتنی خواہش انہیں دارالحکومت میں بسنے کی تھی.اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنیاد چھوٹی رہی اور عمارت بڑی ہو گئی اور چھوٹی بنیاد پر بڑی عمارت قائم نہیں رہ سکتی.ہر انسان کے اندر بعض خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور بعض برائیاں بھی.اگر وہ بعض غلطیاں کر جاتا ہے تو وہ بعض اچھی باتیں بھی کرتا ہے.ہٹلر جو جرمنی کا سابق لیڈر تھا اور جس نے اپنی قوم کی ترقی کے لئے بڑی جدوجہد کی.اگر اس کے اندر اسلام ہوتا تو وہ یقیناً بہت بڑا آدمی ہوتا مگر بوجہ اس کے کہ اس کی تربیت کرنےوالا مذہب نہیں تھا وہ بہت سے غلطیوں کا شکار ہوا اور وہ قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کی بجائے اُسے تنزل میں دھکیلنے کا موجب ہو گیا.وہ چونکہ انجینیئرتھا اس لئے تعمیر سے تعلق رکھنے والی باتیں اس کے لئے زیادہ نصیحت کا موجب ہوا کرتی تھیں اس نے اپنی کتاب ’’مائنے کامف‘‘ (MEIN KAMPH صفحہ ۸۰ تا ۹۶) میں جس میں وہ اپنا پروگرام پیش کرتا ہے لکھا ہے اور اس بات پر لمبی بحث کی ہے کہ یورپ میں اگر کوئی قوم بڑھنے کا حق رکھتی ہے تو وہ صرف جرمن قوم ہے اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتا ہے کہ جو بڑی عمارت ہو وہ بڑی بنیاد پرہی قائم ہو سکتی ہے.تم اگر چارفٹ چوڑی بنیاد رکھو اور اُس پر چھ فٹ چوڑی دیوار بنا دو تو دیوار گر جائے گی لیکن اگر چار فٹ بنیاد رکھو اور تین فٹ چوڑی دیوار
Page 30
بنائو تو وہ زیادہ مضبوط ہو گی.مضبوط عمارتیں بنانے کے لئے ضروری ہے کہ بنیادیں چوڑی رکھی جائیں سو مربع فٹ میں عمارت کھڑی کرنی ہو تو سوا سو مربع فٹ میں بنیاد رکھنی چاہیے.چنانچہ دیکھ لو اہرام مصر ہزاروں سال سے کھڑے ہیں جس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مثلث شکل میں بنائے گئے ہیں ان کی چوٹی صرف چند مربع گز کی ہے لیکن بنیاد ہزاروں مربع گز میں ہے.یہ عمارتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی سینکڑوں سال قبل کی بنی ہوئی ہیں اور کسی نے ان کی مرمت تک نہیں کی لیکن وہ اب تک قائم ہیںاس کی یہی وجہ ہے کہ وہ مثلث شکل میں بنائی گئی ہیں.نیچے بنیادیں پچاس پچاس ایکڑزمین میں ہیں.اور اوپر چوٹی صرف چند مربع گز کی ہے.بوجھ توازن کے ساتھ قائم رہتا ہے اور عمارتیں گرتی نہیں.ہٹلر کہتا ہے کہ جرمن اور ملکوں سے بڑا ہے.اس کی آبادی آٹھ کروڑ ہے.انگلینڈ کی آبادی چار کروڑ ہے.سپین کی آبادی چار کروڑ ہے.فرانس کی آبادی چار کروڑ ہے.اٹلی کی آبادی چار کروڑ ہے.اگر یہ ممالک پھیلنا شروع کریں تو چار کروڑ سے اوپر نکل کر ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور باہر کی آبادیاں ان سے طاقتور ہونے لگیں گی.لیکن جرمن کی بنیاد بڑی ہے اور اس کا خیال تھا کہ اس بنیاد کو بڑا کرنے کے لئے روس کے بھی چند حصے لے لئے جائیں تاکہ دوسرے ممالک کو جب فتح کیا جائے تو وہ اس کے حصے بن سکیں اس پر غالب نہ آسکیں.مگر یہ گُر مسلمانوں نے نہیں پہچانا حالانکہ قرآن کریم نے انہیں یہ ُگر بتادیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھوائی اور دوسری طرف حکم دے دیا کہ لوگ چاروں طرف سے یہاں آئیں اور حج کریں.اسی طرح عمرہ کا حکم دیا اور اس طرح انہیں سال کے سارے حصوں میں مکہ آنے کی طرف توجہ دلائی.اسی طرح مدینہ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جگہ کے رہنے والے اپنے نمائندے مدینے بھیجا کریں تا وہ یہاں رہ کر دینی تعلیم حاصل کریں.مگر مسلمانوں نے اس ُگر کو نہ سمجھا اور ان کا ہر سیاسی مرکز مذہبی مرکز سے زیادہ آباد رہا.اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا کثیر طبقہ سیاسی مرکز کی طرف جاتا تھا اور مذہبی مرکز کمزور رہتا تھا.میرے نزدیک اسلام کو اتنا نقصان اور کسی چیز نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان قاہرہ دمشق اور بغداد نے پہنچایا یا جتنا نقصان اصفہانؔ اور ریّؔ نے پہنچایا، یا جتنا نقصان بخارؔا اور مروؔ نے پہنچایا.ان شہروں نے لوگوں کی توجہ مذہبی مراکز سے ہٹا کر اپنی طرف کر لی.اگر سب سے بڑے شہر مکہ اور مدینہ ہوتے تو یہ خرابی پیدا نہ ہوتی یونیورسٹیاں بغداد میں بنیں حالانکہ ان کاصحیح مقام مدینہ تھا جامعہ ازہر قاہرہ میں بنا حالانکہ اس کا صحیح مقام مکہ تھا.پس جو قوم اپنی روحانیت اور علمی طاقت کو پھیلانا چاہتی ہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا مرکز زیادہ سے زیادہ وسیع اور مضبوط ہو.اسی امر کی طرف حَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَ لُّوْا وُجُوْھَکُمْ شَطْرَہٗ میں اشارہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی
Page 31
گئی ہے کہ تم ہمیشہ اپنی توجہ مکہ کی طرف رکھو اور وہاں کے رہنے والوں کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو.کیونکہ مکہ مکرمہ حج اور عمرہ اور دوسرے دینی اغراض و مقاصد کے لئے جمع ہونے کی جگہ ہے.اگر وہاں فساد ہوا یا لوگ اچھے نہ رہے تو وہاں آنے والے بھی بُرا اثر لئے بغیر نہیں رہ سکتے.درحقیقت مرکز جتنا زیادہ مضبوط ہو اسی قدر جماعت کی تنظیم مضبوط ہوتی ہے اور جماعت روحانی لحاظ سے بھی ترقی کرتی چلی جاتی ہے.پس باہر کے لوگوں کو مرکز کا خاص خیال رکھنا چاہیے.اور مرکز والوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ہمیشہ نیکی اور روحانیت میں ترقی کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے.لِئَلَّا یَکُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّۃٌ.اس کے بعد فرماتا ہے ہمارے ان احکام کی غرض یہ ہے کہ کفار کو کوئی ایسی دلیل نہ مل جائے جس کی وجہ سے تمہیں ان کے مقابلہ میں شرمندگی اٹھانی پڑے.بے شک روحانی لوگوں کو اس بات کی کوئی پروا نہیں ہوتی.وہ کہتے ہیں اگرلوگ اعتراض کرتے ہیں تو بے شک کریں ہمیں ان کے اعتراضوں کی کیاپروا ہے مگر جو ادنیٰ درجہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بڑی بات ہوتی ہے.وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم پر فلاں اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح وہ بعض دفعہ بددل ہو کر علٰیحدہ ہوجاتے ہیں.ان کو فرمایا اچھا ہم تمہارے سپرد یہ کام کرتے ہیں تم اسے ہمت کے ساتھ سرانجام دو تاکہ دشمنوں کی طرف سے تم پر کوئی الزام باقی نہ رہے.یہ الزام پانچ وجوہ کی بنا پرلگایا جا سکتا ہے.اوّل یہود کی کتب میں لکھا تھا کہ آنے والا موعود دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ مکہ کو فتح کرے گا.(استثناء باب ۳۳ آیت ۲) اگر مسلمان مکہ فتح نہ کرتے تویہود کہہ سکتے تھے کہ یہ پیشگوئی اس نبی کے ذریعہ پوری نہیں ہوئی اس لئے ہم اسے کس طرح مان لیں(۲) پھر وہ یہ بھی اعتراض کر سکتے تھے کہ اس بارہ میں خود قرآن کریم کی پیشگوئیاں بھی غلط گئیں.مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّکَ اِلیٰ مَعَادٍ (القصص:۸۶) یعنی وہ خدا جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیاہے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ تجھے اس مقام کی طرف ضرور َلوٹا کر لائے گا.جس کی طرف لوگ حج اور عمرہ کے لئے بار بار َلوٹ کر آتے ہیں.پس اگر مکہ فتح نہ ہوتا تو مخالفین اسلام کو اس اعتراض کا موقعہ ملتا.کہ علاوہ توریت کی پیشگوئی کے خود قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں بھی پوری نہ ہوئیں جو فتح مکہ سے تعلق رکھتی تھیں.(۳) اگر تحویل قبلہ نہ ہوتی تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم ؑ نے جس نبی کے لئے دعا کی تھی اس کا تعلق تو بیت اللہ سے ضروری تھا اور اس نے اس گھر کی آبادی کے لئے آنا تھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک غیر جگہ پر بیٹھا ہے اور کعبہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں.پھر ہم یہ کیونکر سمجھیں کہ وہ دعائے ابراہیمی کا
Page 32
مصداق ہے؟ (۴)اگر مکہ فتح نہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرسکتے تھے کہ اس نبی کی غرض تو توحید پھیلانا تھی مگر خانہ کعبہ میں تو تین سو ساٹھ بُت رکھے ہوئے ہیں(بخاری کتاب المغازی باب این رکز النبی الرأیة یوم الفتح) پھر یہ پیشگوئی کس طرح پوری ہوئی کہ وہ اس گھر کو پاک کرے گا؟ (۵) اگر مکہ فتح نہ ہوتاتو یُعَلِّمُھُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ (البقرة:۱۳۰) والی پیشگوئی کے پورا نہ ہونے پر بھی اعتراض ہوتا اور کہا جاتا کہ اس رسول نے تو مکہ کے لوگوں کی اصلاح کرنی تھی پھریہ پیشگوئی کسی طرح پوری ہوئی؟غرض اگر فتح مکہ یا اصلاحِ مکہ نہ ہوتی تو دشمن کے لئے کئی قسم کے اعتراضات کا موقعہ تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم دے دیا کہ تم مکہ فتح کرو.اور یہ خیال رکھو کہ وہاں کوئی خرابی پیدا نہ ہو ورنہ دشمن کے ہاتھ میں ایسی دلیل آجائے گی جس کا تم کوئی جواب نہیں دے سکو گے.ہاں اگر تم مکہ فتح کر لو تو پھر اُس کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ تم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا.اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْھُمْ.یہ استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی.اگر متصل مانا جائے تو اِس کے معنے یہ ہوں گے کہ تم مکہ کو فتح کرو تاکہ لوگوں کی طرف سے تم پر کوئی الزام نہ رہے سوائے اُن لوگوں کے جو ظالم ہیںیعنی وہ لوگ تو پھر بھی شرارتوں میں حصہ لیتے رہیں گے.اور باتیں بناتے رہیں گے مگر ان کی وہ باتیں قابل اعتناء نہیں ہوں گی.اور اگر حجت کے معنے غلبہ کے کئے جائیں تو پھر یہ استثناء منقطع ہو گا.اور اس کے معنے یہ ہوں گے کہ جو لوگ اِن میں سے ظالم ہوں تم اُن سے مت ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ہی ڈرو کیونکہ تمہارے غلبہ کی وجہ سے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے.(ج) عربی زبان میں اِلَّا کے معنے وَلٰکِنْ کے بھی ہوتے ہیں.جیسے کہتے ہیں.مَالَکَ عَلَیَّ حُجَّۃٌ اِلَّا اَنْ تَظْلِمَنِیْ یعنی تجھے میرے خلاف کسی قسم کی کوئی حجت حاصل نہیں ہاں اگر تو مجھ پر ظلم کرے تو یہ علیحدہ بات ہے.اس لحاظ سے اِس کے معنے یوں ہوں گے کہ فتح مکہ کے بعد لوگوں کے ہاتھ میں کوئی حجت تو نہیں رہے گی لیکن اگر وہ پھر بھی اعتراض کریں گے تو ظلماًہی کریں گے ورنہ اس میں کوئی معقولیت نہیں ہو گی.جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے.اِلَّا واؤ عاطفہ کے معنے بھی دیتا ہے اور مابعد کو پہلے کے ساتھ شریک کرتا ہے اس لحاظ سے اس کے معنے یہ ہوں گے کہ وَلَا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْامِنْھُمْ.یعنی فتح مکہ کے ذریعہ مخالفین اسلام پر ایسی حجت ہوجائے گی کہ ظالموں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے اور وہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکیں گے.وَلِاُ تِمَّ نِعْمَتِیْ عَلَیْکُمْ.فرماتا ہے یہ حکم میں نے اس غرض کےلئے بھی دیا ہے تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں.اس جگہ نعمت سے مراد اسلام ہے اور اُس کے اتمام سے مراد اُسے مستحکم طور پر قائم کر دینا ہے یہ پروگرام
Page 33
بھی فتح مکہ کی اغراض میں سے تھا.چنانچہ جو نہی مکہ فتح ہوا.تمام عرب سے وفود آنے شروع ہوگئے.اور صلح کا ہاتھ بڑھانے لگے (بخاری کتاب المغازی باب مقام النبیؐ بمکة زمن الفتح).آخر اِسی فتح کے نتیجہ میں سارا عرب مسلمان ہو گیا.اور پھر عربوں نے ایک قلیل ترین مدت میں ساری دنیا میں اسلام پھیلادیا.اور وہ نعمت اسلام جو خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کےلئے نازل فرمائی تھی دنیا میں مستحکم طور پر قائم ہو گئی.پھر فرمایا.وَلَعَلَّـکُمْ تَھْتَدُوْنَ.فتح مکہ کا ایک فائدہ تمہیں یہ بھی ہو گا کہ تم ہدایت پاجاؤگے.یعنی تمہاری قوم داخل اسلام ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کےلئے ہدایت کے دروازے کھول دے گا.ورنہ بلحاظ افراد تو فتح مکہ سے پہلے ہی کئی لوگ ایمان لا چکے تھے.مگر باقی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر اس نبی نے مکہ فتح کر لیاتو یہ اور اس کا مذہب سچا ہے اور اگر یہ مکہ فتح نہ کر سکا تو جھوٹا ہو گا(بخاری کتاب المغازی باب مقام النبیؐ بمکة زمن الفتح).چنانچہ جب فتح مکہ ہوئی تو عرب کی تمام اقوام سمجھ گئیں کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اسلام قبول کرنے کے لئے دُور دُور سے وفود آنے شروع ہوگئے.حتّٰی کہ اشد ترین دشمنوں میں سے بھی بعض فتح مکہ کے بعد بیعت میں داخل ہو گئے اِس کی بیّن مثال ہمارے سامنے ہندہ کی ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو سزا کے طور پر قتل کرنے کا حکم دیا تھا اُن میں وہ بھی شامل تھی.مگر وہ بڑی ہوشیار عورت تھی.گھر میں چھپ کر بیٹھ گئی اور باہر نہ نکلی.جب عورتوں کی بیعت ہونے لگی تو چونکہ اس وقت تک پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا.اس لئے اُس نے بھی چادر اوڑھ لی اور اُن کے ساتھ شامل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لئے آگئی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ تھا کہ اِن عورتوں میں ہندہ بھی موجود ہے.آپ نے بیعت لیتے وقت یہ فقرہ فرمایا کہ کہو ہم شرک نہیں کریں گی.اس پر ہندہ جھٹ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ !کیا اب بھی ہم شرک کر سکتی ہیں؟ آپ اکیلے تھے اور مقابل پر آپ کی ساری قوم اور تمام عرب مع اپنے بتوں کے تھے جن سے وہ بزعم خود مدد لیتے تھے.لیکن آپ نے اکیلے ہونے کے باوجود اپنے ایک معبود کی مدد سے مکہ فتح کر لیا.اب کیسے ممکن ہے کہ ہم شرک کریں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کیا ہندہ ہے؟ ہندہ فوراً بول اٹھی کہ یا رسول اللہ ! اب آپ کچھ نہیں کر سکتے.اب میں آپ کی بیعت کر چکی ہوں (السیرة الحلبیة الجزء الثالث فتح مکّة شرفھا اللہ تعالٰی).غرض فتح مکہ ایک ایسانشان تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہندہ جیسی شدید دشمن عورت نے بھی سمجھ لیا کہ اب سچائی بالکل عیاں ہو گئی ہے.دوسری وجہ اقوام عرب کے اسلام قبول کرنے کی یہ تھی کہ عرب کے لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ مکہ کو کوئی
Page 34
جھوٹے مذہب والا آدمی فتح نہیں کر سکتا اور اگر کوئی کوشش کرے گاتو تباہ ہو جائے گا اور اس کی تائید میں اُن کے سامنے ایک تازہ واقعہ بھی تھا.اور وہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی پیدائش سے پہلے یمن کے گورنر ابرہہ نے مکہ فتح کرنے کی کوشش کی.لیکن باوجود ایک کثیر فوج اپنے ساتھ رکھنے کے ناکام رہا.اور آخر اس کی فوج میں ایسی وبا پھیلی کہ تمام فوج تباہ ہو گئی اور وہ ناکامی اور نامرادی کی حالت میں واپس چلا گیا (السیرة النبویة لابن ہشام أمر الفیل و قصة النساء).غرض عرب کے رہنے والے چونکہ قریب کے زمانہ میں اس بات کا تجربہ کر چکے تھے کہ بیت اللہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے اور کوئی شخص اسے بزور فتح نہیں کر سکتا.اس لئے جب آپ نے مکہ والوں کو مغلوب کر لیا تو اس کامیابی نے انہیں یقین دلادیا کہ یہ شخص سچا ہے اور اس کا مذہب بھی سچا ہے اور وہ جوق درجوق آپ پر ایمان لے آئے.بخاری کی ایک حدیث جو حضرت عمر وبن سلمہ سے مروی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ فتح مکہ کے منتظر تھے.چنانچہ لکھا ہے کَانَتِ الْعَرَبُ تُلَوِّ مُ بِاِ سْلَا مِھِمُ الْفَتْحَ فَیَقُوْلُوْنَ اُتْرُکُوْہُ وَقَوْمَہٗ فَاِنَّہٗ اِنْ ظَھَرَ عَلَیْھِمْ فَھُوَ نَبِیٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا کَانَتْ وَقْعَۃُ اَھْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ کُلُّ قَوْمٍ بِاِسْلَامِھِمْ (بخاری کتاب المغازی باب مقام النبیؐ بمکة زمن الفتح ) یعنی عرب لوگ فتح مکہ کا انتظار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے لوگو ! اس نبی اور اس کی قوم کو چھوڑ دو.اگر یہ نبی دوسروں پر غالب آگیا تو پھر یہ ضرور سچا ہے.چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر غالب آگئے تو ہر قوم نے دوڑتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیا اور وفود در وفود لوگ بیعت میں داخل ہوگئے.لَعَلَّکُمْ تَھْتَدُوْنَ میں یہی بات بیان کی گئی ہے.کہ تمہاری قوم کا اسلام لانا فتح مکہ کے ساتھ وابستہ ہے جب مکہ فتح ہو گیا تو تمہاری ساری قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی.پھر جیسا کہ اوپربتایا جا چکا ہےلَعَلَّکُمْ تَھْتَدُوْنَ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ فتح مکہ کے نتیجہ میں تمہیں اپنے رشتہ دار اور دوست سب مل جائیں گے اور آپس کی لڑائیاں اور تفرقہ دور ہو جائے گا.گویا تین قسم کے انعامات تم پر نازل ہو ںگے.اوّل.لِئَلَّا یَکُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّۃٌ.تمہیں فتح مکہ کے بعد ذہنی طور پر اطمینان حاصل ہو جائے گا.اور دشمن کا مونہہ ہر قسم کے اعتراضات سے بند ہو جائے گا.دوم.وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِیْ عَلَیْکُمْ.یہ مادی انعام ہے کہ تمہیں حکومت مل جائے گی.بادشاہت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی.اور اسلام مستحکم طور پر پہلے عرب اور پھر عرب سے نکل کر ساری دنیا میں قائم ہو جائے گا.سوم.لَعَلَّکُمْ تَھْتَدُوْنَ.اس میں قلبی انعام کا ذکر کیا کہ رشتہ داروں کی جدائی کی وجہ سے جو تمہارے دلوں
Page 35
میں بے اطمینانی اور اضطراب ہے وہ بھی دور ہو جائے گااور تمہاری قوم بھی اسلام میں داخل ہو جائے گی.غرض بتایا کہ یہ تین قسم کے انعامات تمہیں ملیں گے کیونکہ وہ لوگ جو روحانیت میں اعلیٰ مقام نہیں رکھتے بالعموم پوچھا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں کام کیا تو ہمیں کیا ملے گا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تین قسم کے انعامات تمہیں اس کے بدلہ میں ملیں گے.اور پہلے گروہ کو اس گروہ کے ساتھ اس لئے شامل کر لیا گیا ہے کہ یہ انعامات انہیں بھی ملنے والے تھے.ورنہ وہ کسی بدلہ کےلئے کام نہیں کرتے اور نہ انہیں انعامات کی کوئی لالچ ہوتی ہے.وہ صرف اس لئے کام کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے.پس یہ تکرار نہیں بلکہ ایک زائد مضمون بیان کرنے کے لئےاسے دُہرایا گیا ہے.اور یہ آیت بھی اپنے اندر فتح مکہ کا ہی مضمون رکھتی ہے.چنانچہ اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ سورۃ فتح میں فتح مکہ کی جو اغراض بتائی گئی ہیں وہی اس جگہ بھی بیان کی گئی ہیں.وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا.لِّیَغْفِرَ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَاَ خَّرَ وَیُتِمَّ نِعْمَتَہٗ عَلَیْکَ وَیَھْدِ یَکَ صِرَاطًا مُّسْتَقِیْمًا (الفتح : ۲.۳) یعنی ہم نے تجھے ایک کھلی کھلی فتح بخشی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تیرے متعلق کئے گئے وہ گناہ بھی جو پہلے گذر چکے ہیں ڈھانک دے گااور جواب تک ہوئے نہیں لیکن آئندہ ہونے کا امکان ہے اُن کو بھی ڈھانک دے گا.اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور تجھے سیدھا راستہ دکھائے گا.اِس آیت میں بتایا گیا ہے کہ فتح مکہ کی تین اغراض ہیں.اوّل دشمن کے اعتراضوں کو دور کرنا.جیسے فرمایا لِیَغْفِرَ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّ مَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَاخَّرَ.اس جگہ مِنْ ذَنْبِکَ سے اعتراضات ہی مراد ہیں.کیونکہ کبھی غیر کے خیال کو بھی دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں.جیسے کہتے ہیں.میرا قصور یہ ہے یعنی تمہارے خیال میں میرا قصور یہ ہے.قرآن کریم میں آتا ہے وَلَھُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ (الشعراء :۱۵) اُن کے نزدیک میں نے ایک گناہ کیا ہے.پس لِیَغْفِرَ لَکَ اللّٰہُ مَا تَقَدَّ مَ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا تَاَخَّرَ کا مطلب یہ ہے کہ اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے دشمن جوتم پر اعتراض کیا کرتاتھا کہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا اور وہ الزام دُور ہو جائے گا.اور صرف اسی وقت نہیں بلکہ آئندہ بھی یہ دلیل ہمیشہ تجھ پر اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کرتی رہے گی.فتح مکہ کی دوسری غرض اتمام نعمت بتائی ہے اور تیسری غرض یَھْدِ یَکَ صِرَ اطًا مُّسْتَقِیْمًا میں یہ بتائی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت میں ترقی عطا فرمائے گا.یہی تین اغراض اس جگہ بھی بیان فرمائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ تم مکہ کو فتح کروتاکہ دشمنوں کا تم پر کوئی الزام نہ
Page 36
رہے.اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر وں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ.سورۃ فتح اور اِن آیات کے تقابل سے صاف ظاہر ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے اور دونوں میں فتح مکہ پر زور دینا اور اُس کے فوائد کو بیان کرنا مقصود ہے.كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ (اُسی طرح) جس طرح ہم نے تم میں تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے.يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَؕۛ۰۰۱۵۲ جو تم (پہلے) نہیں جانتے تھے.حل لغات.کَمَا کے ایک معنے تو وہ ہیں جو عام طور پر کئے جاتے ہیں.یعنی ’’جیسا کہ ‘‘ یہ مشابہت کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے ایک دوسرے معنی لِمَا کے بھی ہیں یعنی ’’اس لئے ‘‘ (بحرمحیط) جیسے ایک شاعر کہتا ہے ع لَا تَشْتُمِ النَّاسَ کَمَا لَا تُشْتَمْ یعنی تو لوگوں کو گالی نہ دے اس لئے کہ وہ تجھ کو گالی نہ دیں.تفسیر.کَمَا کے معنے اگر ’’جیسا کہ‘‘کے سمجھے جائیں تو اس آیت کے یہ معنے بنتے ہیں کہ جس نعمت کا پیچھے ذکر ہوا ہے اُس کا ہم تم پر ویسے ہی اتمام کریں گے جیسا کہ ہم نے تم میںاپنے اس رسول کو جو دعائے ابراہیمی کا موعود ہے بھیج کر اپنے احسان کو مکمل کیا ہے.درحقیقت ابراہیمی دعا کے دو حصے تھے.ایک حصہ تو اُن میں رسول بھیجنے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور دوسرا حصہ ایک پاکیزہ اور مقدس جماعت تیار کرنے کے متعلق تھا.ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مطلب نہ تھا کہ رسول تو آجائے مگر قوم بے شک گمراہ ہی رہے یا رسول تو آجائے مگر قوم کو تقدیس حاصل نہ ہو.پس ضروری تھا کہ ابراہیمی دعا کو پورا کرنے کے لئےجہاں رسول بھیجا گیا وہاں دعا کے دوسرے حصوں کو بھی پورا کیا جاتا اور ایک ایسی پاکیزہ
Page 37
جماعت قائم کی جاتی جو خدا تعالیٰ کے دین کے لئے ہر قسم کی قربانیوں پر آمادہ رہنے والی ہو.اور اگر کَمَا بمعنے لِمَا ہو تو اس صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم نے یہ حکم تمہیں اس لئے دیا ہے کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور اس طرح تم کو پاک کرتا اور مدارج عالیہ کی طرف بڑھاتا ہے اور تم کو شریعت سکھاتا ہے اور پھر وہ احکام شریعت کی باریک در باریک حکمتوں اور پوشیدہ اسرار سے واقف کرتا ہے.اور صرف وہی تعلیم نہیں دیتا جو پہلے صحیفوں میں پائی جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایسی تعلیم دیتا ہے جو تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھی.پس تم لوگ میرا ذکر کرو تاکہ میں بھی تمہیں اپنے دربار میں جگہ دوں اور میرے انعامات پرجو اس رسول کے ذریعے تم پر کئے گئے ہیں شکر بجا لاتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو.یوں تو دنیا کے تمام مذاہب کی ابتداء انبیاء ؑ کی ذات سے ہی ہوئی ہے لیکن کوئی مذہب بھی ایسا نہیں جس نے ایسے نبی کو پیش کیا ہو جو تمام امور دینیہ کی حکمتوں کو بیان کرنے کا مدعی ہو اور جسے تمام بنی نوع انسان کےلئے اُسوئہ حسنہ کے طور پر پیش کیا گیا ہو.عیسائیت جو سب سے قریب کا مذہب ہے.وہ تو مسیح کو ابن اللہ قرار دے کر اِس قابل ہی نہیں چھوڑتی کہ اُس کے نقش قدم پر کوئی انسان چلے کیونکہ انسان خدا جیسا نہیں ہو سکتا.باقی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سو تورات انہیں اسوۂ حسنہ کے طور پر پیش نہیں کرتی.نہ تورات اور انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو مذہبی حکمتوں کے بیان کرنے کا ذمہ دار قرار دیتی ہے.لیکن قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے یُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ.کہ یہ نبی تمہیںاحکام الٰہیہ اور اس کی حکمتیں بتاتا ہے.پس اسلام ممتاز ہے اس بات میں کہ اس کا نبی دنیا کے لئے اسوۂ حسنہ بھی ہے اور جبرسے اپنے احکام نہیں منواتا بلکہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اپنے اتباع کے ایمانوں کو مضبوط کرنے اور اُن کے جوش کو زیادہ کرنے کے لئے یہ بھی بتاتا ہے کہ اُس نے جو احکام دئیے ہیں اُن کے اندر ملت افراد ملت اور باقی نوع انسان کے لئے کیا کیا فوائد مخفی ہیں.یہ وہی دعائے ابراہیمی ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے.مگر اس میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعامیں دو فرق ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے.حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ یہ تھے کہ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (البقرۃ : ۱۳۰)یعنی اے خدا ! تو ان میں انہی سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے.انہیں کتاب کی تعلیم دے ان پر احکام الٰہیہ کی حکمت
Page 38
واضح کرے.اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے.گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تلاوتِ آیات پھر تعلیم کتاب پھر تعلیم حکمت اور پھر تزکیہ کو رکھا تھا.مگر یہاں پہلے تلاوت آیات پھر تزکیہ پھر تعلیم کتاب و حکمت کو بیان کیا گیا ہے.پس طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے.کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ دعائے ابراہیمی کی ترتیب اس اصول پر مبنی ہے کہ دنیا میں جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ تلاوت آیات سے کام لیتا ہے یعنی اس وحی کو پیش کرتا ہے جو اس پر نازل ہوتی ہے.اور اُن معجزات اور نشانات کو پیش کرتا ہے جو اُس کی تائید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیںاس کے بعد آہستہ آہستہ احکام نازل ہوتے ہیں تو اُن احکام کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں اور آخر معجزات و نشانات دیکھنے، دلائل و براہین پر غور کرنے اوراُن کی حکمتوں کو سمجھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی جماعت کو ایک تقدس عطا فرماتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ دوسروں پر غالب آجاتی ہے.مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری ترتیب کو مدِّ نظر رکھا ہے.یعنی ایمانیات اور روحانیات سے تعلق رکھنے والی باتوں کو اس نے پہلے لے لیا ہے اور علوم ظاہری سے تعلق رکھنے والی باتوں کو بعد میں بیان کر دیا ہے.تزکیہ چونکہ قلب سے تعلق رکھتا ہے اور تلاوت آیات بھی ایمان سے تعلق رکھتی ہے اس لئے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو لے لیا جو ایمانیات اور روحانیات سے تعلق رکھتی ہیں.چنانچہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ معرفت کے لحاظ سے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ انسان کو ایسی آنکھیں عطا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کا مشاہدہ کرنے والی ہوں.اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان نشانات کا مشاہدہ اُس کے اندر ایسا تزکیہ پیدا کر دے کہ اس کا دل خدا تعالیٰ کا عرش بن جائے.اور صفات الٰہیہ اس کے آئینہ قلب میں منعکس ہو جائیں.جب معرفت کا نور انسانی قلب کو ایسا جلا بخشتا ہے کہ اُس میں کوئی نفسانی کدورت اور آلائش باقی نہیں رہتی تو اس وقت وہ خدا کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے اور یہی انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے.اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تلاوت آیات کے بعد تزکیہ نفوس کو دوسرے امور پر مقدم رکھا ہے.تزکیہ کے بعد تعلیم کتاب اور حکمت کا ذکر فرمایا ہے.جو ظاہری علوم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اور ا نہیں آخر میں رکھ کراس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ احکام اور اُن کی حکمتیں اصل مقصود نہیں بلکہ اصل مقصود تزکیہ نفس اور اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے.یہی وجہ ہے کہ اگراللہ تعالیٰ کانبی کسی شخص کو آواز دے اور وہ جسے بلایا گیا ہو اُس وقت نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اُسی وقت نماز توڑ دے اور خدا تعالیٰ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائے کیونکہ وہ صفات الٰہیہ کا کامل مظہر ہوتا ہے اور اس کی آواز گویا خدا کی آواز ہوتی ہے.مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک شخص کو آواز دی.وہ اس وقت نماز پڑھ
Page 39
رہا تھا.اُس نے نماز توڑ دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا.لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور خدا کا نبی اُسے بلائے تو وہ نماز بھی توڑ سکتا ہے.اِسی طرح حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ایسی حالت میں آواز دی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے بھی نماز توڑ دی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے.معلوم ہوتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ استدلال قرآن کریم کی اس آیت سے کیا تھا کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ(الانفال: ۲۵) یعنی اے مومنو! تم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کےلئے فوراً حاضر ہو جایا کرو جبکہ وہ تمہیں زندہ کرنے کے لئے پکارے.غرض نماز اصل مقصود نہیں اور نہ ہی روزہ اور حج اور زکوٰۃ وغیرہ مقصود ہیں.یہ سب ذرائع ہیںخدا تعالیٰ تک پہنچنے کے اور یہ سب ذرائع ہیںنفس انسانی کو ہر قسم کی روحانی آلائشوں سے پاک کرنے کے.اگر کسی کا دل پاک نہیں تو خواہ زبان سے وہ ہزار بار کتاب اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر ے اس کا یہ دعویٰ ایک رائی کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتا.تزکیہ کے بعد تعلیم کتاب اور حکمت میں بھی تعلیم کتاب کو اس لئے مقدم رکھا گیا ہے کہ اعلیٰ ایمان والا شخص صرف یہ دیکھتا ہے کہ آیا اُس کے محبوب نے فلاں کام کرنے کو کہا ہے یا نہیں.اگر کہا ہو تو وہ بغیر سوچے سمجھے اس کام کو اختیار کر لیتا ہے.لیکن جو اعلیٰ ایمان نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس کام کی غرض کیا ہے اور اس میں حکمت کیا ہے؟ جب تک مجھے اس کی حکمت نہ بتائی جائے گی میں عمل نہیں کرو ںگا.غرض ایک سچے اور مخلص مومن کےلئے صرف یہی کافی ہوتا ہے کہ اُس کا ربّ اُسے حکم دے رہا ہے.وہ خدا کی آواز سنتا اور اس کی طرف دوڑپڑتا ہے.لیکن فلسفی حکمت کا سراغ لگاتا ہے اور جب تک اُس کا دماغ تسلی نہ پائے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا.ایک ماں کو اس کے بچہ کی خدمت کےلئے اگر صرف دلائل دئیے جائیں اور کہا جائے کہ اگر تم خدمت نہیں کرو گی تو گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور یہ ہو گا اوروہ ہوگا تو یہ دلائل اُس پر ایک منٹ کےلئے بھی اثر انداز نہیں ہوسکتے.وہ اگر خدمت کرتی ہے تو صرف اس جذبہ محبت کے ماتحت جو اس کے دل میں کام کر رہا ہوتا ہے.اِسی لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایمان العجائز ہی انسان کو ٹھوکر وں سے بچاتا ہے.ورنہ وہ لوگ جو حیل وحجت سے کام لیتے ہیںاور قدم قدم پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں حکم کیوں دیا گیا ہے اور فلاں کام کرنے کو کیوں کہا گیا ہے وہ بسا اوقات ٹھوکر کھا جاتے ہیں.اور اُن کا رہا سہا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے.لیکن کامل الایمان شخص اپنے ایمان کی بنیاد مشاہدہ پر رکھتا ہے.وہ دوسروں کے دلائل کو توسن لیتا ہے مگر ان کے اعتراضات کا اثر قبول نہیں کرتا
Page 40
کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کو اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے.منشی اروڑے خان ؓ صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اُن کا ایک لطیفہ مجھے یاد ہے.وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تم مولوی ثناء اللہ صاحب کی ایک دفعہ تقریر سن لو تب تمہیں پتہ لگے کہ مرزا صاحب سچے ہیں یا نہیں؟ وہ کہنے لگے میں نے ایک دفعہ اُن کی تقریر سنی.بعد میں لوگ مجھ سے پوچھنے لگے.اب بتاؤ کیا اتنے دلائل کے بعد بھی مرزا صاحب کو سچا سمجھا جا سکتا ہے؟میں نے کہا میں نے تو مرزا صاحب کا مونہہ دیکھا ہوا ہے.اُن کا مونہہ دیکھنے کے بعد اگر مولوی ثناء اللہ صاحب دو سال تک بھی میرے سامنے تقریر کرتے رہیں تب بھی اُن کی تقریر کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جھوٹے کا مونہہ تھا.بے شک مجھے اُن کے اعتراضات کے جواب میں کوئی بات نہ آئے میں تو یہی کہو ں گا کہ حضرت مرزا صاحب سچے ہیں.غرض حکمت کا معلوم ہونا ایک کامل مومن کےلئے ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ایمان عقل کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ مشاہدہ پر مبنی ہوتا ہے.اسی لئے اُسے احکام کی حکمت سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی.ہاں جس کا ایمان صرف دلائل کی حد تک ہو اُسے حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے.غرض ایمان کامل مشاہدہ کی بنا پر ہوتا ہے اور ایمان ناقص حکمت کی بنا پر.کامل الایمان لوگوں کےلئے نبی کا تلاوت ِآیات اور تزکیہ ہی کافی ہوتا ہے.اور آیات کی حکمت اور اس کی غرض معلوم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے.وہ نبی کی آواز کافی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول کےلئے دیوانہ وار کام شروع کر دیتے ہیں.ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے کہ آپ ؐ نے دوران تقریر میں فرمایا.بیٹھ جاؤ.کیونکہ اُس وقت کناروں پر کئی لوگ کھڑے تھے.اُس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ گلی میں تھے اور مسجد کی طرف آرہے تھے جونہی یہ آواز آپ کے کان میں پہنچی آپ وہیں بیٹھ گئے اور پھر گھسٹتے گھسٹتے دروازہ کی طرف چل پڑے.یہ اچنبھے کی بات تھی کسی نے انہیں بچوں کی طرح گھسٹتے دیکھ کر کہا.آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تو یہ تھا کہ اندر والے بیٹھ جائیں یہ مطلب تو نہیں تھا کہ گلی میں چلنے والے بھی بیٹھ جائیں.حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا.کہ اگر وہاں پہنچتے پہنچتے میری جان نکل جائے تو میں خدا تعالیٰ کو کیا جواب دوں گاکہ خدا تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ایک آواز آئی تھی جس پر میں نے عمل نہ کیا.(کنز العمال باب فی فضائل الصحابة......)اب بظاہر یہ بات حکمت کے خلاف نظر آئے گی مگر عشق کا رنگ ہی اَور ہوتا ہے.عاشق حکمتوں کو نہیں دیکھتابلکہ جو کچھ محبوب کہے اُسے ماننے کےلئے تیار ہو جاتا ہے.تو یاد رکھنا چاہیے کہ حکمت تابع ہے تعلیم کے اور تعلیم تابع ہے تزکیہ کے اور تزکیہ تابع ہے آیات اللہ کے.اصل خدا تعالیٰ کی ذات ہے پھر اُس کا مقام ہے جو خدا نما ہو.پھر اُس سے اتر کر وہ ذرائع ہیںجو انسان کو خدا نما بنانے والے ہیں.پھراُن سے اتر کر وہ
Page 41
محرکات ہیں جو لوگوں کو عمل کی ترغیب دلاتے ہیں.پس یہ ترتیب چھوٹے بڑے درجہ کے لحاظ سے ہے.لیکن دعائے ابراہیمی میں اس ترتیب کو مدِّ نظر رکھا گیا ہے جس سے انسان ترقی کرتا ہے.چنانچہ پہلے اُسے دلائل دیئے جاتے ہیں.پھر ان کے بعد فرائض بتائے جاتے ہیں.اس کے بعد فرائض کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں.اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے انہیں تزکیہ حاصل ہو جائے گا.دعائے ابراہیمی اور اس آیت میں دوسرا فرق یہ ہے کہ وہاں دعا کے بعد کہا تھا اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ اور اس جگہ ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.اس کی یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزیز وحکیم صفات کے واسطہ سے دعا کی تھی.کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اپنے خیالات کے مطابق مانگ رہا ہوں.مگر مجھے معلوم نہیں کہ اُس وقت کی ضرورت کیا ہوگی ؟پس تو اپنی طاقت اور حکمت سے کام لے کر جس چیز کی اس وقت ضرورت ہو وہ دیجئیو.لیکن یہاں خدا تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ فرماکراس دعا کی قبولیت کا ذکر کر دیاکہ ابراہیم ؑ نے عزیز اور حکیم دو صفات کے واسطہ سے جو دعا مانگی تھی وہ پوری ہو گئی.اور نہ صرف یہ نبی وہ کام کر رہا ہے جو ابراہیم ؑ نے کہے بلکہ ایسے رنگ میں کر رہا ہے کہ پہلے کسی نبی نے نہیں کئے.کیونکہ اس زمانہ کی ضرورت ایسی ہی اعلیٰ درجہ کی تعلیم چاہتی تھی.پس دعائے ابراہیمی کامل طور پر پوری ہو گئی.وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رسول تم کو وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے.یعنی اس کی تعلیم صرف اُنہی اچھی تعلیمات پرمشتمل نہیں جو پہلی کُتب میں پائی جاتی ہیں بلکہ اس سے زائد اس میں ایسی باتیں بھی ہیں جو پہلے دنیا کو معلوم نہیں تھیں.قرآن کریم نے دوسری جگہ اس امر کو محکمات اور متشابہات کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے.چنانچہ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَ اُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ (آل عمران: ۸)یعنی تجھ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اِس کی بعض آیتیں تو محکم ہیں جو اس کتاب کی جڑہیں اور کچھ اور ہیں جو متشابہ ہیں.اس میں متشابہات سے مراد وہ باتیں بھی ہیں جو پہلی تعلیموں سے ملتی جلتی ہیں.مثلاً روزہ رکھنا.یہ حکم اپنی ذات میں متشابہہ ہے کیونکہ یہ تعلیم پہلے بھی پائی جاتی تھی.اسی طرح قربانیوں کا حکم بھی متشابہہ ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ(الحج :۳۵)یعنی دنیا کی ہر قوم کے لئے ہم نے قربانی کا ایک طریق مقرر کیا تھا تاکہ وہ اُن جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو بخشے ہیں اللہ کا نام لیں اورانہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں.غرض قرآن کریم کی کچھ تعلیمیں تو ایسی ہیں جو پچھلی تعلیموں سے ملتی ہیں اور لازماً ملنی چاہئیں.مثلاً پہلے نبیوں نے کہا تھا کہ سچ بولا
Page 42
کرو.تو کیا قرآن یہ کہتا کہ سچ نہ بولا کرو جھوٹ بولا کرو؟ پس اس میں لازماً کچھ ایسی تعلیمیں ہیں جو پہلی تعلیموں سے ملتی ہیں.اور انہی کا نام متشابہات رکھا گیا ہے لیکن کچھ تعلیمیں ایسی بھی ہیں جن میں اسلام دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں ایک یگانہ اور منفرد حیثیت رکھتا ہے اور وہی محکمات ہیں.اگر وہ تعلیمیں بھی جو موسیٰ ؑ اور عیسیٰ ؑ لائے محکم ہوتیں تو پھر قرآن کریم کے نزول کی کوئی ضرورت نہ تھی.پس يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ میں قرآن کریم کی اسی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ صرف وہی تعلیم نہیں دیتا جو پہلے صحیفوں میںپائی جاتی ہےبلکہ ایسی تعلیم بھی دیتا ہے جو اُن سے زائد ہے اور جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھی.فَاذْكُرُوْنِيْۤ۠ اَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوْا لِيْ وَ لَا تَكْفُرُوْنِؒ۰۰۱۵۳ پس( جب میں اس قدر فضل کرنےوالا ہوں تو) تم مجھے یاد رکھو.میں (بھی )تمہیں یاد کرتا رہوںگا.اور میرے شکرگزار بنو اور میری ناشکری نہ کرو.تفسیر.ذکر کے معنے یاد کرنے کے ہوتے ہیں لیکن ہر یاد ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی بلکہ الگ الگ رنگ اپنے اندر رکھتی ہے.جس کے اندر طاقت نہیں ہوتی اس کی یاد صرف تمنا اور خواہش اور التجا ء کا حکم رکھتی ہے.جیسے ایک شخص کا رشتہ دار دور گیا ہوا ہو.اور وہ اُس کو یاد کرے تو چونکہ اُس میں طاقت نہیں ہوتی کہ اُس کو بلا سکے.خواہ بسبب احتیاج کے خواہ بسبب مصالح کے اس لئے یہ یاد صرف التجاء اور خواہش ہی ہو گی یا ایک بچہ جو پنگھوڑے میں پڑا ہوا اپنی ماںکو یاد کرتا اور روتا ہے تو اس کی یاد بھی صرف اس تمنا اور خواہش تک ہی محدود ہوتی ہے کہ اُس کی ماں اُس کے پاس آئے.اور اسے اپنی گود میں اُٹھالے لیکن ایک یاد ایسے شخص کی ہوتی ہےجس میں کچھ طاقت تو ہوتی ہے لیکن پوری طاقت نہیں ہوتی.ایسا شخص اپنے مقصد کے حصول کے لئے کچھ کوشش بھی کرتا ہے.جیسے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور اُس وقت اپنی ماں کو یاد کرتا ہے تو وہ اپنی ماں سے ملنے کی صرف خواہش ہی نہیں کرتا بلکہ عملی طور پر اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے.پھر ایک یاد وہ ہے جو بادشاہ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی رعایا کے کسی فرد کو یاد کرتا ہے.ایسی صورت میں اُس کی یاد التجاء نہیں ہوتی بلکہ ایک زبردست طاقت ہوتی ہےجس کے ذریعہ وہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اُس کی یاد عملاً پوری ہو جاتی ہے.غرض جب ایک ادنیٰ آدمی بڑے کو یاد کرے تو اُس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا اسے اپنے پاس بلالے.اور یہ التجاء ہوتی ہے.لیکن
Page 43
جب بڑا آدمی ادنیٰ کو یاد کرے تو اس کے معنے اس کو بلانے کے ہوتے ہیں.کیونکہ اُس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے.اس کی ایسی ہی مثال ہے.جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے.وَلَکُمْ فِیْھَا مَا تَشْتَھِیْ اَنْفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیْھَا مَا تَدَّعُوْنَ(حٰمٓ السجدة : ۳۲)یعنی جنت میں جو کچھ تمہارا جی چاہےگا تم کو ملےگا اور جو کچھ تم مانگو گے وہ تم کو عطا کیا جائے گا.یہ خواہش بھی ایک طاقت اور قوت پر دلالت کرتی ہے.کیونکہ اِدھر خواہش پیدا ہو گی اور اُدھر اللہ تعالیٰ اُس خواہش کو پورا کرنے کا سامان پیدا فر مادے گا.دنیا میں اگر کسی کو کہا جائے کہ بادشاہ سلامت تمہیں یاد کرتے ہیں تو کیا مجال ہے کہ وہ فوراً اپنا کام نہ چھوڑ دے اور بادشاہ کی ملاقات کے لئے نہ چل پڑے.کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو میری خیر نہیں.پس اس یاد میں ایک زبردست کشش اور طاقت ہوتی ہے اور جسے یاد کیا جاتا ہے وہ اس کی طرف کھچا چلا جاتا ہے.پس اگر بادشاہ کی یاد عام یاد کے علاوہ معنی رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے بھی اَور معنے ہو سکتے ہیں.پس فَاذْكُرُوْنِيْۤ۠ کے یہ معنے ہیں کہ تم میرے ملنے کی خواہش کرومجھے یاد رکھو اور میرے قرب کے حصول کے لئے کوشش کرو اور جب تم ایسا کرو گے تو اَذْکُرْکُمْ میں بھی تمہیں یاد کروںگا.جس کے یہ معنے ہیں کہ تم میری طرف کھچے چلے آؤگے.میرے قرب کے دروازے تمہارے لئے کھل جائیںگے.دنیا میں جب ایک معمولی بادشاہ بھی اس طرح یاد نہیں کرتا کہ وہ دوسرے کا نام لینا شروع کردے تو خدا تعالیٰ کی یاد کے یہ معنے کس طرح ہو سکتے ہیں کہ وہ اس کے نام کا وظیفہ پڑھنے لگ جائے.پس اَذْکُرْکُمْ کے یہ معنے ہیں کہ تم ہمارے حضور کھچے چلے آؤگے اور ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤگے.یہ مراد نہیں کہ ہم تمہارا نام لینے لگ جائیں گے.عربی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اَمِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ یَذْکُرُکَ.یعنی امیرالمومنین آپ کو یاد فرماتے ہیں.پُرانے زمانہ میں جب کسی کو پیغام دینا ہوتا تھا تو یہی الفاظ کہتے تھے.اور اس سے یہ مراد نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے.بلکہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم فوراًاُن کے حضور پہنچ جاؤ.پس فَاذْكُرُوْنِيْۤ۠ اَذْكُرْكُمْکے یہ معنے ہیں کہ تم میرا قرب حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو.جب تمہاری محبت اپنے کمال کو پہنچ جائے گی تو اس کے نتیجہ میں میں بھی تمہیں اپنا قرب دے دوںگا.یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بندہ کا ذکر عموماً تین قسم کا ہوتا ہے.اوّل کسی اچھی یا بری بات کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کو یاد کر لینا.جیسے گناہ کی تحریک ہو تو اَسْتَغْفِرُاللّٰہَ کہنا.کوئی مصیبت پہنچے تو اِنَّالِلّٰہِ کہنا.خوشی کی خبر ملے تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کہنا.دوم دوسرے کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا.جیسے کسی مصیبت زدہ کا واقعہ سُنا تو اُس کے لئے دعا کی اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اُس نے اپنے فضل سے ہمیں اس قسم کے مصائب سے بچا رکھا ہے.سوم خدا تعالیٰ کے متعلق باتیںکرنایعنی اپنی مجالس میں خدا تعالیٰ کے رحم اور کرم کے متعلق گفتگو کرنا.دشمنوں کے اعتراضات کا
Page 44
جواب دینا.اُس کے نام کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کرنا.اور بار بار اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرنا تاکہ اس کے نتیجہ میں (۱)خدا تعالیٰ کی صفات انسان کے دل پر نقش ہوں (۲)اور پھر وہ مٹیں نہیں بلکہ ہمیشہ قائم رہیں (۳)اور انسان کے ہر قول و عمل سے ان کا ظہور ہو.پھر ذکر کے ایک معنے چونکہ عزت اور شہرت کے بھی ہوتے ہیں.اس لئے اَذْکُرْ کُمْ کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیںکہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کو یادرکھیں گے اور اس کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں عزت اور شہرت عطا فرمائے گا.اور آخرت میں بھی انہیں اپنے لازوال قرب سے نوازے گا.پھر فرماتا ہے وَ اشْكُرُوْا لِيْ.تم میرا شکر کرو.یعنی تمہیں صرف اس بات پر مطمئن نہیں ہوجانا چاہیے کہ تم خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہو بلکہ تمہارا یہ کام بھی ہے کہ تم گذشتہ انعامات پر اُس کا شکر ادا کرتے رہو اور تمہارے اعمال اور تمہاری عبادات ان انعامات پر مبنی ہو ں جو ہم پہلے تم پر کر چکے ہیں.وَلَا تَکْفُرُوْنِ اور ہم نے جو تم پر انعامات نازل کئے ہیں.ان کی ناقدری مت کرو.حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کی نسبت فرمایا کہ وہ دوزخ میں مردوں کی نسبت زیادہ جائیںگی.عورتوں نے پوچھا.یا رسول اللہ ! اس کی کیا وجہ ہے ؟ آپ ؐ نے فرمایا اِس کی یہ وجہ ہے کہ تم میں ناشکری کا مرض زیادہ پایا جاتا ہے(بخاری کتاب الایمان باب کفران العشیر و کفر دون کفر).ناشکری کے معنے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اُن کو موقعہ اور محل پر استعمال نہ کیا جائے.خدا تعالیٰ نے کان اس لئے دئیے ہیں کہ خدائے رحمٰن کی باتیں سُنی جائیں لیکن لوگ ان کو گناہ کی باتیں سننے کے لئے استعمال کرتے ہیں.آنکھیں اُن کو اس لئے دی گئی ہیں کہ وہ ان کے ذریعہ علم و عرفان حاصل کر یں.مگر کوئی ان کے ذریعہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنی دولت کیوں ہے ؟ اور کوئی کسی اور ناجائز جگہ پر ان کو استعمال کرتا ہے.اسی طرح زبان ان کو اس لئے دی گئی ہے کہ وہ اُس سے اچھی گفتگو کریں.اور خدا تعالیٰ کا ذکر کریں مگر اُسے بُری اور ناپسندیدہ باتوں کے لئے استعمال کرتے ہیں.مثلاً گالیاں دیتے ہیں.چغل خوری کرتے ہیں.غیبت کرتے ہیں.جھوٹ بولتے ہیںاور اس طرح خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں.پس فرمایا کہ تم میری نعمتوں کی قدرکرو.اور جو انعامات میں نے تم پر کئے ہیںاُن کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو اور یہ اقرار کرو کہ ہم ان انعامات کو صحیح طور پر استعمال کریں گے.ان کا غلط استعمال کر کے خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی بے حرمتی نہیں کریںگے.
Page 45
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو.صبر اور دُعا کے ذریعہ سے (اللہ کی) مددمانگو.اللہ(تعالیٰ) یقیناً مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۰۰۱۵۴ صابروں کے ساتھ (ہوتا) ہے.حلّ لُغات.اَلصَّبْرُ صبر کے اصل معنے تو رُکنے کے ہیں.مگر اس لفظ کے استعمال کے لحاظ سے اس کے مختلف معانی ہیں.چنانچہ اس کے ایک معنے تَرْکُ الشِّکْوٰی مِنْ اَلَمِ الْبَلْوٰی لِغَیْرِ اللّٰہِ (اقرب).یعنی جب کوئی مصیبت اور ابتلاء وغیرہ انسان کو پہنچے اور اسے تکلیف ہو تو خدا تعالیٰ کے سوا دوسروں کے پاس اس کی شکایت نہ کرنا صبرکہلاتا ہے.ہاں اگر وہ خدا تعالیٰ کے حضور اپنی بے کسی کی شکایت کرتا ہے تو یہ صبر کے منافی نہیں.چنانچہ لغت کی کتاب اقرب الموارد میں لکھا ہے.اِذَادَعَااللّٰہَ الْعَبْدُ فِیْ کَشْفِ الضُّرِّ عَنْہُ لَا یُقْدَحُ فِیْ صَبْرِہٖ.جب بندہ خدا تعالیٰ سے اپنی مصیبت کے دور کرنے کے لئے دعا کرتا ہے تو اُس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اُس نے بے صبری دکھائی ہے.کُلّیاتِ ابی البقاء میں لکھا ہے کہ صبر انسان کی ایک اعلیٰ درجہ کی صفت ہے اور مختلف حالات میں اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں.اَمَّا فِی الْمُحَارَبَۃِ فَشَجَاعَۃٌ اگر لڑائی میں انسان استقامت سے کام لے اور مشکلات سے نہ گھبرائے تو اُسے شجاعت کہتے ہیں.وَفِیْ اِمْسَاکِ النَّفْسِ عَنِ الْفُضُوْلِ اَیْ عَنْ طَلْبِ مَا یَفْضَلُ عَنْ قَوَامِ الْمَعِیْشَۃِ فَقَنَاعَۃٌ وَعِفَّۃٌ (اقرب) اور اگر ضروریات زندگی سے زائد چیزوں کے متعلق انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دے اور نفس کو روک لے تو اُسے قناعت اورعفت کہتے ہیں.چونکہ صبر کے اصل معنے رُکنے کے ہوتے ہیں.اس لئے محققین لغت نے لکھا ہے کہ اَلصَّبْرُ صَبْرَ انِ صَبْرٌ عَلٰی مَاتَھْوِیْ وَصَبْرٌ عَلٰی مَاتَکْرَہُ (اقرب).یعنی صبر کی د۲و قسمیں ہیں.جس چیزکی انسان کو خواہش ہو اس سے باز رہنا بھی صبر کہلاتا ہے.اور جس چیز کو ناپسند کرتا ہو لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ آجائے.اُس پر شکوہ نہ کرنا بھی صبر کہلاتا ہے.حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم اوراحادیث سے ثابت ہے صبر اصل میں تین قسم کا ہوتا ہے.(۱) پہلا صبر تو یہ ہے کہ انسان جزع فزع سے بچے.جیسے قرآن کریم میں آتا ہے.وَاصْبِرْ عَلٰی مَآ اَصَابَکَ (لقمان: ۱۸) تجھے جو کچھ تکلیف
Page 46
پہنچے اس پر تو صبر سے کام لے.یعنی جزع فزع نہ کر (۲)دوسرے نیک باتوں پر اپنے آپ کو روک رکھنا.یعنی نیکی کو مضبوط پکڑ لینا.اِن معنوں میں یہ لفظ اس آیت میں استعمال ہواہے.فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْھُمْ اٰثِمًا اَوْکَفُوْرًا.(الدھر: ۲۵)یعنی اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور انسانوں میں سے گنہگار اور ناشکر گذار کی اطاعت نہ کر.پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر احکام قرب الٰہی کے حصول کے لئے دئیے گئے ہیں.اُن پر استقلال سے قائم رہنا اور اپنے قدم کو پیچھے نہ ہٹانا بھی صبر کہلاتا ہے.(۳)تیسرے معنے اس کے بدی سے رکے رہنے کے ہیں.ان معنوں میں یہ لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے.وَلَوْ اَنَّھُمْ صَبَرُوْا حَتّٰی تَخْرُجَ اِلَیْھِمْ لَکَانَ خَیْرًا لَّھُمْ وَاللّٰہُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (الحجرات : ۶) یعنی اگر وہ تجھے بلانے کے گناہ سے باز رہتے اور اس وقت تک انتظار کرتے جب تک کہ تو باہر نکلتا تو یہ ان کے لئے بہت اچھا ہوتا مگر اب بھی وہ اصلاح کر لیں تو بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.زیر تفسیر آیت میں چونکہ کوئی قرینہ نہیں اس لئے یہاں تینوں معنے مراد لئے جائیں گے.اور اِس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ ہر ایک کام کے دو ذرائع ہوتے ہیں.ایک جسمانی اور ایک روحانی اور دونوں ذریعوں کو استعمال کرنے سے کامیابی ہوتی ہے.پس تم دونوں ذریعوں کو استعمال کرو.یعنی (۱)خدا تعالیٰ کی راہ میں جو تکالیف پہنچیں اُن کو بہادری سے برداشت کرو(۲) جو ذرائع کسی کام کے حصول کے لئے مقرر ہیں.اُن کو حاصل کرنے اور استعمال کرنے میں کوشاں رہو.(۳)جو باتیں اِس کام میں روک ہوتی ہوں.اُن سے بچنے کی کوشش کرتے رہو.دوسرا ذریعہ روحانی بتایا کہ دعا کرو.اور عبادت میں لگ جاؤ.اَلصَّلٰوۃ صَلوٰۃٌ کے اصل معنے عبادت الٰہی کے ہیں.لیکن چونکہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے.اس لئے نماز کو بھی صلوٰۃ کہتے ہیں.(۲) صَلوٰۃٌ کا لفظ دعا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.(۳) دین کو بھی صلوٰۃکہتے ہیں.(۴) رحمت کو بھی صلوٰۃ کہتے ہیں.(۵) استغفار کو بھی صلوٰۃ کہتے ہیں.(۶) حسنِ ثنا کے معنوں میں بھی صلوٰۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے.(۷) صلوٰۃکے معنے درود بھیجنے کے بھی ہوتے ہیں(اقرب).صَلَّی سے مشتق ہے اور اس کا وزن فَعْلَۃٌ ہے.الف وائو سے منقلب ہے.صَلَّی (یُصَلِّیْ) کے معنے دعا کرنے کے ہیں اور اَلصَّلٰوۃُ کے اصطلاحی معنے عِبَادَۃٌ فِیْہَا رَکُوْعٌ وَسُجُوْدٌ کے ہیں یعنی اس مخصوص طریق سے دعا کرنا جس میں رکوع و سجود ہوتے ہیں جس کو ہماری زبان میں نماز کہتے ہیں.اس کے علاوہ اس کے اور بھی کئی معانی ہیں جو بے تعلق نہیں بلکہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں.چنانچہ اس کے دوسرے معنےمندرجہ ذیل ہیں اَلرَّحْمَۃُ رحمت.اَلدِّیْنُ شریعت.الْاِسْتِغْفَارُبخشش مانگنا.اَلدُّعَاءُ دعا (اقرب)
Page 47
اَلتَّعْظِیْمُ بڑائی کا اظہار.اَلْبَرَکَۃُ برکت (تاج) وَالصَّلٰوۃُ مِنَ اللّٰہِ اَلرَّحْمَۃُ ، وَمِنَ الْمَلَآ ئِکَۃِ اَلْاِسْتِغْفَارُ، وَمِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ الدُّعَاءُ.وَمِنَ الطَّیْرِ وَالْھَوَامِّ اَلتَّسْبِیْحُ.اور صَلٰوۃ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنے رحم کرنے کے ہوتے ہیں.اور جب ملائکہ کیلئے استعمال ہو تو اس وقت اس کے معنے استغفار کے ہوتے ہیں اور جب مومنوں کے لئے بولا جائے تو اس کے معنے دعا یا نماز کے ہوتے ہیں اور جب پرند اور حشرات کیلئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے تسبیح کرنے کے ہوتے ہیں.وَھِیَ لَا تَکُوْنُ اِلَّا فِی الْخَیْرِ بِخَـلَافِ الدُّعَاءِ فَاِنَّہٗ یَکُوْنُ فِی الْخَیْرِ وَالشَّرِّ.اور لفظ صلٰوۃ صرف نیک دعا کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن لفظ دعا، بد دعا اور نیک دعا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے.لفظ صلٰوۃ کے ایک معنے حُسْنُ الثَّنَاءِ مِنَ اللّٰہِ عَلَی الرَّسُوْلِ کے بھی ہیں یعنی جب صَلَّی فعل کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو اور مفعول آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہو تو اس وقت اس کے معنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم کی بہترین تعریف کے ہوتے ہیں.(اقرب) وَیُسَمّٰی مَوْضِعُ الْعِبَادَۃِ الصَّلٰوۃُ اور عبادت گاہ کو بھی اَلصَّلٰوۃ کہہ دیتے ہیں (مفردات) پس یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ کے معنے ہوںگے (۱) نماز کو باجماعت ادا کرتے ہیں (۲) نماز کو اس کی شرائط کے مطابق اور اس کے اوقات میں صحیح طو رپر ادا کرتے ہیں (۳) لوگوں کو نماز کی تلقین کر کے مساجد کو بارونق بناتے ہیں (۴) نماز کی محبت اور خواہش لوگوں کے دلو ںمیں پیدا کرتے ہیں (۵) نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں اور اس پر پابندی اختیار کرتے ہیں (۶) نماز کو قائم رکھتے ہیں یعنی گرنے سے بچاتے رہتے اور اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں.تفسیر.اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ سے مراد وہی جنگیں ہیں جن کا فتح مکہ کے ساتھ تعلق تھا کیونکہ صبر اور صلوٰۃ کا تعلق تکلیفوں کے وقت سے ہی ہوتا ہے.پہلے یہود کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کے موقعہ پر فرمایا تھا کہ صبر اور صلوٰۃ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے اِس کی مدد مانگو(البقرة : ۴۶) اب فتح مکہ کے ذکر پر فرماتا ہے کہ جنگ میں تمہیں تکلیفیں تو بے شک ہوں گی اور تمہارے اقرباء بھی شہید ہوں گے لیکن اس تکلیف پر بزدلی نہ دکھانا بلکہ استقلال سے قربانیاں کرتے چلے جانا اور تکالیف کے مواقع پر اپنے خدا سے صبر اور دعا کے ذریعے مدد مانگنا.اس آیت میں یہ عظیم الشان مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کے لئے کسی تکلیف پر رونا یا اس کے دل میں مدد کا احساس پیدا ہونا منع نہیں.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو کئی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور تم اُن کو محسوس بھی کرو گے لیکن مَیں تمہیں اس درد کا علاج یہ بتاتا ہوں کہ صبر اور دعا کو کام میں لاؤ.یہ نہیں فرمایا کہ قطعی طور پر
Page 48
کسی تکلیف کو محسوس ہی نہ کرو.احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ فوت ہو نے لگا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے.ایک صحابی ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ! کیاآپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا دل سخت نہیں بنایا (بخاری کتاب المرضٰی باب عیادة الصبیان).غرض درد کا احساس منع نہیں.ہاں ہمت ہار کر کام چھوڑ دینا اورجزع فزع کرنا منع ہے.اِسی لئے فرمایا کہ تکالیف تو ہوںگی اورتلوار تو چلے گی اور تمہاری گردنیں بھی کٹیں گی لیکن ان پر صبر سے کام لینا اور استقلال سے اپنے کام میںلگے رہنا.ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تمہیں غم کا احساس نہیں ہونا چاہیے.یہ ایک طبعی جذبہ ہے جو روکا نہیں جا سکتا.ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان قربانیوں میں استقلال سے حصہ لو اور اپنے پائے ثبات میں کبھی لغزش نہ آنے دو.مگر پھر فرمایا کہ یہ تو دنیوی تدابیر ہیں.تمہارا اصل کام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو.اور دعاؤں سے اُس کی مدد چاہو.جب تک تم خدا تعالیٰ پر کامل توکل نہیں کرو گے اور اُس سے دعائیں کرنا اپنا معمول نہیں بناؤ گے اُس وقت تک تمہیں فتح حاصل نہیں ہو گی.دیکھو ایک نادان اور کم عقل بچہ بھی جب اُسے کوئی ڈراتا ہے تو فوراً اپنی ماں کے پاس بھاگ جاتا ہے اور ماں خواہ کتنی ہی کمزور ہو وہ اس کے پاس جا کر اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتا ہے.اِسی طرح ایک مومن پر بھی جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کی پناہ صرف خدا تعالیٰ کا ہی وجود ہوتا ہے.اسی لئے صلوٰۃکا تعلق روحانی ہونے کے لحاظ سے خدا تعالیٰ سے ہے.اور صبر کا تعلق جسمانی ہونے کے لحاظ سے انسانی تدابیر سے ہے.صبر میں جبری طور پر خدا تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اورصلوٰۃ میں عشقیہ طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے.مشکلات اور مصائب ہم خود پیدا نہیں کرتے بلکہ دشمن مشکلات اور مصائب لاتا ہے.اور ہم انہیں برداشت کرتے ہیںاور خدا تعالیٰ کو نہیں چھوڑتے لیکن نماز اور دعا طوعی عبادت ہے.نماز ہمیں کوئی جبری نہیں پڑھاتا بلکہ ہم خود پڑھتے ہیں.پس صبر میں ہم جبری طور پر خدا تعالیٰ کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں اورصلوٰۃمیں طوعی طور پر اس کا اظہار کرتے ہیں اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیںتو محبت کامل ہو جاتی ہے.اور خدا تعالیٰ کا فیضان جاری ہو جاتا ہے.صبر کے جو معنے اوپر بیان کئے گئے ہیں.اُن کے لحاظ سے اس ا ٓیت کا مطلب یہ ہے کہ (۱)اے مومنو! جب تم پر خدا تعالیٰ کی راہ میں مصائب اور مشکلات آئیں تو تم گھبرایا نہ کرو اور نہ اُن پر شکوہ کا اظہار کیا کرو.(۲)اے مومنو! جو باتیں خدا تعالیٰ کے قرب میں روک ہیں تم اُن سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہا کرو.(۳) اے مومنو! جب تم کو وہ احکام دئیے جائیں جن کے ذریعہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے.تو تم ان پر عمل کرنے میں سستی نہ دکھایا کرو بلکہ استقلال سے اُن پر عمل کیا کرو.
Page 49
یہ تین باتیں روحانی مدارج کے حصول کے لئے ممد ہیں تم ان باتوں کو مدِّنظر رکھو.اگر تم ایسا کرو گے تو جو کام تمہارے سامنے ہیں اُن کے پورا کرنے میں تمہیں کامیابی ہوگی اور تمہارا مقصد تمہیں حاصل ہو جائے گا.اسی طرح صلوٰۃ کے معنوں کو مدِّنظر رکھتے ہوئے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ (۱) اے مومنو! تم نماز کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی مدد حاصل کرو.(۲) اے مومنو! تم دعائوں کے ذریعہ اس کی مدد حاصل کرو.(۳) اے مومنو! دین پر استقلال کے ساتھ قائم ہو جانے کے ذریعے سے اس کی مدد حاصل کرو.(۴) اے مومنو!تم خدا تعالیٰ کی مخلوق پر رحم اور شفقت کر کے اس کی مدد حاصل کرو.(۵) اے مومنو! تم خدا تعالیٰ کے حضور استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اس کی مدد حاصل کرو.(۶) اے مومنو! تم خدا تعالیٰ کے رسول پر درود بھیج کر اُس کی مدد حاصل کرو.گویا یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے حصول کے ذرائع ہیں.سورۃ فاتحہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ تم اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ کہا کرو.یعنی اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں.اور تجھ سےہی مدد چاہتے ہیں.اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ُگربتایا ہے کہ مدد کس طریق سے حاصل کی جاسکتی ہے.فرماتا ہے وہ ذرائع یہ ہیں کہ ایک تو دین کے راستہ میں جو مشکلات اور مصائب پیش آئیں اور جو قربانیاں تمہیں کرنی پڑیں اُن سے گھبرایا نہ کرو.دوسرے ان امور سے جن سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتا ہے رُکے رہو.تیسرے وہ قربانیاں جو قرب الٰہی کے حصول کے لئے ضروری ہیں ان کو ترک نہ کرو.اور ان پر استقلال اور دوام اختیار کرو.چوتھے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کے بہترین نتائج پیدا کرے اور اُن کو قبول فرماتے ہوئے تمہیں غلبہ بخشے.پانچویں غرباء سے ہمدردی اور شفقت کا سلوک کرو تا مخلوق خدا کو آرام پہنچانے کی وجہ سے خدا تعالیٰ بھی تم سے خوش ہو.چھٹے خدا تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی طلب کرتے رہو.ساتویں انبیاء پر درود بھیجا کرو.کیونکہ اُن کے ذریعے سے ہی تم کو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی توفیق ملی ہے.آٹھویں خدا تعالیٰ کے دین پر استقلال کے ساتھ قائم رہنے کی کوشش کیا کرو.نویںعبادت پر مضبوطی سے قائم رہو.یہ سب امور خدا تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے بیان فرمائے ہیں.پس جو شخص چاہتا ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل ہو اس کے لئے اِن نو باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے.بندے کا صرف اپنے مونہہ سے خدا تعالیٰ کو یہ کہنا کہ الٰہی میری مدد کر کوئی معنے نہیں رکھتا.مدد حاصل کرنے کے لئے پہلے ان ذرائع پر عمل کرنا ضروری ہے.جو شخص گھبرا کر مایوس ہو جاتا ہے اور پھر یہ امید رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اُس کی مدد کے لئے آسمان سے نازل ہوںگے وہ اُس کی مدد حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا.جو شخص خدا تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور ساتھ ہی یہ اُمید رکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اس کے لئے نازل ہوں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا.
Page 50
جو شخص قربانیوں سے ہچکچاتا اور خدا تعالیٰ کی عاید کردہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے قاصر رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا.جو شخص دعا نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ کے حضور عاجزانہ طور پر گڑ گڑاتا نہیں اور اس کے باوجود اس کی معجزانہ تائید کا امیدوار رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا.جو شخص دین کے معاملے میں غیرت سے کام نہیں لیتا اور اس کی ترقی میں ممد نہیں ہوتاوہ دشمنوں کے مقابلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا.جوشخص غرباء اور مساکین پر شفقت نہیں کرتا اور اُن کی مشکلات کو دُور کرنے میں ہاتھ نہیں بٹاتا وہ اپنی مشکلات کے وقت خدا تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا.جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر درود نہیں بھیجتا.اُن کے لئے دعائیں نہیں کرتا اور ان کے احسانات کے شکریہ کا احساس اپنے دل میں نہیں رکھتاوہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنےمیں کبھی کامیاب نہیں ہوتا.جو شخص عبادت اور خدمت دین کے لئے اپنی ساری عمر وقف نہیں کرتا.وہ قرب الٰہی کے اعلیٰ مدارج پانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا.پھر باوجود ان سب باتوں پر عمل کرنے کے جوشخص یہ محسوس نہیں کرتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنے عمل پر اِتراتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا.لوگ منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ لیکن یہ نہیں جانتے کہ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ کہنے کے ساتھ کن کن باتوں کی ضرورت ہے.وہ ڈاکخانہ میں روپے منی آرڈر کرانے کے لئے جاتے ہیں تو منی آرڈر فارم ساتھ لے کر جاتے ہیں.کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک منی آرڈر فارم پُر نہیں کیا جائے گا روپیہ پوسٹ نہیں ہو سکتا.یا وہ ڈاکخانہ میں خط ڈالنے جاتے ہیں تو اس پر ٹکٹ لگاتے ہیں ورنہ وہ بیرنگ کر دیا جاتا ہے.مدرسہ میں داخل ہونے کے وقت وہ فارم پُر کرتے ہیں جو داخلہ کے لئے محکمہ تعلیم کی طرف سے مقرر ہوتا ہے.امتحان کے لئے یونیورسٹی کا فارم پُر کرتے ہیںاور اس میں ذراسی غلطی ہونے سے بھی اُن کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے.اور وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کام خراب نہ ہو جائے.مگر خدا تعالیٰ سے بغیر کوئی فارم پُر کرنے کے اور بغیر کسی شرط پر عمل کرنے کے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ حضور اپنے ملائکہ کی فوج بھیج کر ہماری مدد کیجیئےحالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہاں بھی ایک فارم کی ضرورت ہے.جب تک وہ فارم پُر کر کے اُس پر دستخط نہ کئے جائیں اُس وقت تک خدا تعالیٰ کی نصرت شامل حال نہیں ہو سکتی اور وہ صبر اور صلوٰۃ کا فارم ہے.جب تک صبر اور صلوٰ ۃ کے فارم پر دستخط نہ کروگے تب تک خدا تعالیٰ کی مدد تمہیں حاصل نہیں ہو سکے گی.اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ.اس جگہ اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ کے لفظ کو اُڑادیا ہے.اور صرف مَعَ الصّٰبِرِیْنَکے الفاظ رکھے ہیں.مَعَ الْمُصَلِّیْنَ نہیں فرمایا.اِس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں صابر کا لفظ اپنے اندر استقلال کے معنے رکھتا ہے اور صابر کا لفظ صرف صبر کا قائم مقام نہیں بلکہ صبر اور صلوٰۃ دونوں کا قائم مقام ہے.پس اس کے صرف یہ معنے نہیں کہ
Page 51
اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبرو صلوٰۃ دونوں پر استقلال کے ساتھ قائم رہنے والوں کے ساتھ ہے.کیونکہ دعا بھی وہی قبول ہوتی ہے جو استقلال سے کی جائے.پس اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کے یہ معنے ہیں کہ اگر صبر اور صلوٰۃ کے ذرائع کو استقلال سے استعمال کر و گے تو کامیاب ہو جاؤگے.اِس آیت میں اُن لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے جو کچھ عرصہ تکلیف برداشت کرتے اور یہ کہنے لگے جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تو ہماری سُنتا ہی نہیں.ہم تو اُسے پکار پکار کر تھک گئے اب دعا کرنے کا کیا فائدہ.اور بعض لوگوں کو تو اس قدر ٹھوکر لگتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے ہی منکر ہو جاتے ہیں.پس اللہ تعالیٰ نے اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ کہہ کر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اسی کوحاصل ہوگی جو مشکلات کے وقت استقامت دکھائے گا اور صبر اور صلوٰ ۃ کے ذرائع کو استقلال سے استعمال کرتا چلا جائے گا.وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ١ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے متعلق (یہ) مت کہو کہ وہ مردہ ہیں.(وہ مردہ)نہیں بلکہ زندہ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ۰۰۱۵۵ ہیں مگر تم نہیںسمجھتے.حل لغات.لَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْوَاتٌ.جب قَالَ کے بعد صلہ کے طور پر لام آئے تو اُس کے معنے خطاب کے ہوتے ہیں.چنانچہ جب قَالَ لِفُلَانٍ کہیں تو اس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ اُس نے فلاں کو کہا.اِسی طرح قَالَ لِفُلَانٍکے یہ بھی معنے ہوتے ہیں کہ اُس کے حق میں کہا.پس اس آیت میں دونوں معنے ہیں.یہ بھی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جاتےہیں ان کو مردہ مت کہواور یہ بھی کہ تم اُن کے بارہ میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں.اس آیت میں اَمْوَاتٌ سے پہلے اور بَلْ کے بعد دونوں جگہ ھُمْ محذوف ہے.پس عبارت یوں ہوگی ھُمْ اَمْوَاتٌ بَلْ ھُمْ اَحْیَآءٌ.اَمْوَاتٌ.اَمْوَاتًا.مَیِّتٌ اور مَیْتٌ کی جمع ہے اور مَیِّتٌ اور مَیْتٌکے معنے ہیں اَلَّذِیْ فَارَقَ الْـحَیٰوۃَ جو زندگی سے علیحدہ ہو جاوے (اقرب)اور میّت اسے کہتے ہیں جس پر موت وارد ہو اور موت حیات کے
Page 52
مقابل کا لفظ ہے جو معنی حیات کے ہوں اس کے الٹ معنے موت کے ہوتے ہیں.تَشْعُرُوْنَ.شَعَرَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے.شَعَرَہٗ کے معنے ہیں عَلِمَ بِہٖ اس کو جانا.شَعَرَ لِکَذَا فَطَنَ لَہٗ اس کو خوب سمجھ لیا.عَقَلَہٗ اس کو جان لیا.وَاَحَسَّ بِہٖ اس کو محسوس کیا (اقرب) تاج العروس میں ہے اَلشِّعْرُ ھُوَا لْعِلْمُ بِدَقَائِقِ الْاُمُوْرِ وَ قِـیْلَ ھُوَ الْاِدْرَاکُ بِالْـحَوَاسِ کہ شعر علم کی وہ قسم ہے جس کے ذریعہ سے امور کی باریکیاں معلوم ہو سکیں.اور بعض نے کہا ہے کہ حواس کے ذریعہ سے کسی امر کو معلوم کر لینا شِعْرکہلاتا ہے.پس لَا تَشْعُرُوْنَ کے معنے ہوں گے تم نہیں جانتے.تفسیر.اِس آیت میں خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو اس لئے زندہ کہا گیا ہے کہ اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ جو لوگ مارے جائیں اور اُن کا بدلہ لے لیا جائے اُن کے لئے تو وہ اَحْیَاءٌ کا لفظ استعمال کرتے تھے اور اُن کو زندہ کہتے تھے.لیکن جن مقتولوں کا بدلہ نہ لیا جائے وہ انہیں اَمْوَاتٌ یعنی مردے کہا کرتے تھے.یہ محاورہ اُن میں اس لئے رائج ہوا کہ عربوں میں یہ مشہور تھا کہ جو شخص ماراجائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے اُس کی روح اُلّو کی شکل میں آکر چیختی رہتی ہے اور جب اس کا بدلہ لے لیا جائے تب وہ آرام کرتی ہے.اس سے ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جس مقتول کا بدلہ لے لیا جائے وہ زندہ ہوتا ہے.اور جس کا بدلہ نہ لیا جائے وہ مردہ ہوتا ہے.چنانچہ انہی معنوں میں ایک شاعر حارث بن حلزہ نے کہا ہے کہ ؎ اِنْ نَبَشْتُمْ مَا بَیْنَ مِلْحَۃَ فَالصَّا قِبِ فِیْہِ الْأَ مْوَاتُ وَ الْأَ حْیَآءُ (سبعۃ معلقات قصیدہ نمبر۷) اس میں شاعر فریق مخالف کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے شریف اور معزز ہو مگر ایسا ہرگز نہیں تم ملحہ اور صاقب کے درمیان جہاں ہمارے اور تمہارے در میان جنگ ہوئی تھی جائو اور وہاں قبریں کھود کر دیکھو تو اُن میں تمہیں کچھ مردے دکھائی دیں گے اور کچھ زندہ.یعنی تم نے اپنی قوم کے مقتولوں کا بدلہ نہیں لیا.اس لئے وہ مردہ ہیں مگر ہمارے جو آدمی نکلیں گے وہ بزبان حال بتاتے جائیں گے کہ وہ زندہ ہیں کیونکہ ان کا بدلہ لے لیا گیا ہے.اُن میں اس بارہ میں اتنی غیرت تھی کہ اگر کسی مقتول کا بدلہ نہ لیا جاتا تو وہ اُسے حد درجہ کی بے غیرتی سمجھتے تھے کیونکہ ان میں یہ روایت چلی آتی تھی کہ جس مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی رُوح اُلّو بن کر رات دن چیختی رہتی ہے اور جب اس کا بدلہ لے لیا جائے تب وہ نجات پاتی ہے.پس شاعر کہتا ہے کہ تم ہمارے باپ دادوں کی قبریں کھود کر دیکھو اور ان سے پوچھو کہ ان کا بدلہ لے لیا گیا ہے یا نہیں ہم نے ان کی بجائے دشمن قبیلہ کے کئی کئی اشخاص مار دیئے
Page 53
ہیں.پس ہمارے باپ دادا مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں.اگر اُن میں کچھ لوگ مرے ہوئے نظر آئیں تو ہمارے باپ دادا نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے باپ دادا ہوں گے.غرض جس مقتول کا بدلہ لے لیا جائے اہل عرب کے محاورہ کے مطابق وہ زندہ ہوتا ہے.اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں تم انہیں ُمردہ مت کہو وہ خدا تعالیٰ کے زندہ سپاہی ہیں.اور خدا تعالیٰ ان کا ضرور بدلہ لے گا.چنانچہ اگر ایک صحابیؓ مارا گیا تو اس کے مقابلہ پر مشرکوں کے پانچ پانچ آدمی مارے گئے.اور ہر جنگ میں کفار مسلمانوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہلاک ہوئے سوائے جنگ ِ اُحد کے کہ اس میں بہت سے مسلمان مارے گئے تھے مگر اُن کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جنگوں میں لے لیا.دوسرے معنی محاورہ میں اس کے یہ ہوتے ہیں کہ جس شخص کا کام جاری رکھنے والے لوگ پیچھے باقی ہوں اس کی نسبت بھی کہتے ہیں.مَامَاتَ کہ وہ مرا نہیں اور مردہ اسے کہتے ہیں جو مرے اور اس کا کوئی اچھا اور نیک قائم مقام نہ ہو.چنانچہ عبدالملک بادشاہ نے زہری کے ایک مدرسہ کا معائنہ کیا تو اس مدرسہ کے طلباء میں اصمعی بھی تھے جو بہت بڑے مشہور نحوی گذرے ہیں.بادشاہ نے اصمعی کا امتحان لیا اور اُس سے کوئی سوال پوچھا تو اصمعی نے اس کا نہایت معقول جواب دیا.بادشاہ نے اس کا جواب سن کر خوش ہو کر زہری سے کہا کہ مَامَاتَ مَنْ خَلَفَ مِثْلَکَ کہ وہ شخص نہیں مرا جس نے ایسے لوگ پیچھے چھوڑے ہوں جیسا کہ تو نے چھوڑے ہیں.اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ یہ لوگ مردہ نہیں کہلا سکتے کیونکہ جس کام کے لئے انہوں نے جان دی ہے اس کے چلانے والے لوگ موجود ہیں اور ایک کے مرنے پر دو اس کی جگہ لینے کے لئے تیار ہوتے ہیں.پس ان کے متعلق یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے قائم مقام پیدا کر دیئے ہیں.اور یہ لوگ اپنی تعداد میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں.مردہ تو وہ ہوتا ہے جس کا بعد میں کوئی اچھا قائم مقام نہ ہو مگر ان کے تو بہت سے قائم مقام پیدا ہو گئے ہیں اور آئندہ بھی ایسا ہی ہو گا کہ ہم ان میں سے ایک ایک کی جگہ کئی کئی قائم مقام پیدا کرتے چلے جائیں گے اور وہ قوم کبھی مرتی نہیں جس کے افراد اپنے شہداء کی جگہ لیتے چلے جائیں جو قوم اپنے قائم مقام پیدا کرتی چلی جاتی ہے وہ خواہ کتنی بھی چھوٹی ہو اسے کوئی مار نہیں سکتا.پس فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان مارے گئے ہیں مسلمان مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں.اگر ان میں سے ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے.اگر جنگ بدر میں کچھ مسلمان مارے گئے تو اُحد میں اس سے زیادہ کھڑے ہو گئے.اُحد میں کچھ تکلیف پہنچی اور کچھ مسلمان مارے گئے تو غزوۂ خندق میں اس سے زیادہ کھڑے ہو گئے.اور غزوۂ خندق کے مقابلہ میں فتح مکہ کے موقعہ پر زیادہ لوگ آئے اور اگر فتح مکہ
Page 54
’’ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا جو محض بیجان وجود تھا اور صرف اس میں سے آواز پیدا ہوتی تھی بنا لیا.اور اتنا بھی غور نہیں کیا کہ وہ بولتا نہیں اور نہ انہیں کوئی ہدایت کی بات بتاتا ہے مگر بہر حال انہوں نے اسے اختیار کر لیا اور مشرک ہو گئے.‘‘ (الاعراف : ۱۴۹).’’ اور اس سے (یعنی موسیٰ علیہ السلام کی واپسی سے) پہلے ہارون نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس بچھڑے کے ذریعہ سے تمہارے ایمان کی آزمائش کی گئی ہے.اور تمہارا رب تو رحمٰن ہے.( یعنی کلام ہدایت نازل کرتا ہے حالانکہ یہ بچھڑا تو تم کو کوئی ہدایت نہیں دیتا) پس میری فرمانبرداری کرو اور جو میں تم کو کہتا ہوں اس پر عمل کرو( شرک نہ کرو) اس پر انہوں نے کہا کہ ہم تو جب تک موسیٰ واپس نہ آجائیں اِس بچھڑے کی عبادت میں مشغول رہیں گے.‘‘ (طٰہٰ : ۹۱،۹۲) بچھڑے کے بنانے کے متعلق بائبل اور قرآن مجید کے بیان کا فرق بائبل اور قرآن کریم کے اِس بیان میں بہت بڑا فرق ہے.اوّل تو قرآن کریم بنی اسرائیل کی گھبراہٹ کی وجہ بھی بتاتا ہے.وہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتداءًپہاڑ پر تیس رات رہنے کا حکم دیا گیا تھا ( لازماً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس کا ذکر کر دیا ہو گا) پھر خدا تعالیٰ نے اپنے احسان کو مکمل کرنے کے لئے اس وعدہ کو چالیس رات تک بڑھا دیا (چالیس کا عدد روحانی دنیا میں تکمیل کا عدد ہے) اِس مدّت کے فرق کی وجہ سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ ؑ کے واپس نہ آنے پر گھبراہٹ پیدا ہونے لگ گئی ہو گی.کوئی خیال کرنے لگا ہو گا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں.کوئی سمجھنے لگا ہو گا کہ شاید راستہ کی مشکلات کو دیکھ کر موسیٰ ؑ دھوکا دے کر ہمیں درمیان ہی میں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں.تب انہوں نے بوجہ ایمان میں حدیث العہد ہونے کے اپنے لئے ارد گرد کی مشرک قوموں کی طرح بُت بنانے کی طرف توجہ کی.بائبل کے بیان سے اس گھبراہٹ کی وجہ پر کوئی روشنی نہیں پڑتی.بائبل کے بیان کے خلاف قرآن مجید کا حضرت ہارون ؑ کو شرک سے پاک قرار دینا دوسرے قرآنِ کریم وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ شرک دوسرے اسرائیلیوں نے کیا.ہارون علیہ ا لسلام اس الزام سے کلّی طور پر پاک تھے بلکہ انہوں نے اسرائیلیوںکو شرک سے روکنے کے لئے پوری کوشش کی.بائبل اس کے برخلاف ہارون ؑ کو جو ایک نبی تھے شرک میں نہ صرف شریک بتاتی ہے بلکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیلیوں کے کہنے پر بِلا تردّد انہوں نے بُت بنانے پر رضا مندی ظاہر کر دی اور نہ صرف بچھڑا بنایا بلکہ ساری قوم کو اس کی عبادت کی دعوت دی.لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللہِ العَلِیِّ الْعَظِیْمِ.
Page 55
والوں کو مُردہ مت کہو وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں.یعنی شہید کے اعمال کبھی ختم نہیں ہو سکتے وہ زندہ ہے اور اس کے اعمال ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں.اس نے خدا کے لئے اپنی جان قربان کر دی اور خدا نے نہ چاہا کہ اُس کے اعمال ختم ہو جائیں.کوئی دن نہیں گذرتا کہ تم نمازیں پڑھو اور ان کا ثواب تمہارے نام لکھا جائے اور شہید اُن سے محروم رہے.کوئی رمضان نہیں گذرتا کہ تم اُس کے روزے رکھو اور اُن کا ثواب تمہارے نام لکھا جائے اور شہید اس سے محروم رہے.کوئی حج نہیں کہ تم تکلیف اٹھا کر اس کا ثواب حاصل کرو اور شہید اس ثواب سے محروم رہے.غرض وہ لوگ وہی برکتیں حاصل کر رہے ہیں جو تم کر رہے ہو اور اس طرح خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس طرح تم بڑھتے جا رہے ہو.پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فلسفۂ موت و حیات پر نہایت لطیف رنگ میں روشنی ڈالی ہے.اور بتایا ہے کہ شہادت کا مقام حاصل کرنے والوں کو دائمی حیات حاصل ہوتی ہے.چنانچہ دیکھ لو ! جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی فوجوں نے مارا ہو گا.وہ کس قدر خوش ہوئی ہوں گی اور انہوں نے کس مسرت سے کہا ہو گا کہ لو یہ قصّہ ختم ہو گیا.مگر کیا واقعہ میں وہ قصہ ختم ہو گیا؟ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام حسین ؓ آج بھی زندہ ہیں.مگر یزید کو اس وقت بھی مردہ سمجھا جاتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے رستہ میں قربان ہوتا ہے تو اس کا خون رائیگاں نہیں جاتا بلکہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک قوم لاتا اور اپنے سلسلہ میں داخل کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تم انہیں مردہ مت کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں.خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ اس لئے بھی کہا کہ جب ایک شخص کی جگہ دس کھڑے ہو گئے تو وہ مرا کہاں.اور جب وہ مرا نہیں تو اُسے مردہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ کے مقربین اور اس کی راہ میں شہید ہونے والے کبھی نہیں مرتے.حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے گئے اور پھر وہ زندہ ہی صلیب سے اُتارے گئے.گو جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے بعض نے یہ بھی سمجھا کہ آپ مر گئے ہیں (النساء:۱۵۸).مگر آپ کو صلیب پر لٹکانے والوں کا کیا انجام ہوا؟ اس صلیب پر لٹکانے کے جرم میں آج بھی جب کہ اس واقعہ پر انیس سو سال کا عرصہ گذر چکا ہے یہود صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں.حالانکہ پچاس ساٹھ سال کے بعد لوگ اپنے دادوں پڑدادوں کا نام تک بھول جاتے ہیں.بیسیوں آدمی ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں اور میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ کے دادا کا کیا نام تھا تو وہ بتا نہیں سکتےاور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام تھا اور اگر دادا کا نام لوگ جانتے بھی ہوں تو سو سال پہلے کے آباء کو تو لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک جانتا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش پر انیس سو سال گذر گئے اور آج تک یہودیوں کو پھانسیاں مل رہی ہیں.
Page 56
اسی طرح مکہ کے جن اکابر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہا.کیا آج دنیا میں ان لوگوں کا کوئی نام لیوا ہے؟ اُحد کے مقام پر ابوسفیان نے آواز دی تھی اور کہا تھا کیا تم میں محمد( صلی اللہ علیہ وسلم) ہے؟ اور جب اس کا جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ و سلم) کو مارڈالا ہے.پھر اس نے آواز دی.کیا تم میں ابو بکرؓ ہے؟ اور جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے ابو بکرؓ کو بھی مار ڈالا ہے.پھر اس نے پوچھا کیا تم میں عمرؓ ہے؟ جب اس کا بھی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے عمرؓ کو بھی مار ڈالا ہے.(بخاری کتاب المغازی باب غزوة احد) لیکن آج جائو اور دنیا کے کناروں پر اس آواز دینے والے کے ہمنوا کفار کے سردار ابوجہل کو بلائو اور آواز دو.کہ کیا تم میں ابوجہل ہے؟ تو تم دیکھو گے کہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو کروڑوں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی اور ساری دنیا بول اُٹھے گی کہ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں کیونکہ آپ کی نمائندگی کا شرف ہمیں حاصل ہے.لیکن ابوجہل کو بلانے پر تمہیں کسی گوشہ سے بھی آواز اٹھتی سنائی نہیں دے گی.ابوجہل کی اولاد آج بھی دنیا میں موجود ہے مگر کسی کو جرأت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں ابوجہل کی اولاد میں سے ہوں.شاید عتبہ اور شیبہ کی اولاد بھی آج دنیا میں موجود ہو.مگر کیا کوئی کہتا ہے کہ میں عتبہ اور شیبہ کی اولاد ہوں.پس خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والے کبھی نہیں مرتے بلکہ وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں اور آئندہ نسلیں ان کا نام لے لے کر ان کے لئے دعائیں کرتی ہیں ان کی خوبیوں کو یاد رکھتی ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتی ہیں.اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے متعلق مفسرین سے جو میں اختلاف رکھتا ہوں اس میں میں حق پر ہوں.اگر وہاں فتح مکہ مراد نہ لی جائے بلکہ تحویل قبلہ مراد لیں تو اس آیت کا یہاں کوئی تعلق ہی معلوم نہیں ہوتا.نماز اور قبلہ کے ذکر میں شہداء کا ذکر کیسے آگیا؟ جنگ کے ساتھ شہداء کا ذکر قابلِ تسلیم بھی ہے لیکن تحویل قبلہ کے ساتھ اس کا ذکر بالکل بے جوڑ معلوم ہوتا ہے.پس یہ آیت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ پہلی آیت وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ سے مُراد فتح مکہ ہی ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر فتح مکہ کی غرض سے تمہیں لڑائیاں کرنی پڑیں تو گھبرانا نہیں کیونکہ اس میں تمہاری زندگی ہے اور جو لوگ مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو.کیونکہ وہ زندہ ہیں اور جو لوگ اپنی نادانی سے اُن کو مردہ کہتے ہیں ان کے نفس میں اتنی حِس ہی نہیں کہ وہ اس کی اہمیت کو محسوس کریں اس میں ان معترضین کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ لڑائیوں کی اور اپنی جانوں کو قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھیں اس بینائی سے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو عطا کی ہے محروم ہیں.تم کو کیا معلوم کہ اسلام کی فتح کی بنیاد انہی لوگوں کے ہاتھ سے رکھی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جاتے ہیں.ہاں !
Page 57
مارے جانے والے اس کو خوب سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہید ہونے سے اسلام کو کیا فائدہ ہو گا.چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جابربن عبداللہ ؓ کو دیکھا کہ وہ بہت افسردہ اور غمگین کھڑے ہیں.آپ نے فرمایا تم کیوں غمگین ہو.انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! میرے والد اُحد کی جنگ میں مارے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے پیچھے بہت بڑا عیال اور قرضہ چھوڑا ہے اس لئے میں افسردہ ہوں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں کہ موت کے بعد تمہارے والد کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جب زندہ ہو کر حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے خو ش ہو کر بالمشافہ کلام کیا اور فرمایا.اے میرے بندے! تو مجھ سے جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ میں تجھے دوںگا.انہوں نے عرض کیا حضور میری صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ میں پھر زندہ ہو کر دنیا میں جائوں اور آپ کی ر اہ میں مارا جائوں.اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کر تو سکتا ہوں مگر میں یہ قانون بنا چکا ہوں کہ جو ایک دفعہ مر جائے اس کو دنیا میں واپس نہیں بھیجوں گا.(ترمذی کتاب التفسیر سورۃ آل عمران) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سچا ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا مرنا قوم کو زندہ کرنے کا موجب ہو گا اور آخرت میں بھی ہمارے لئے بہت بڑے ثواب کا موجب ہو گا اس لئے وہ موت کو کوئی خوف والی چیز نہیں سمجھتے.وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دے کر بھی زندہ ہوتے ہیں اور جانیں نہ دینے والے زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں.چنانچہ ڈپٹی عبداللہ آتھم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو انذاری پیشگوئی فرمائی تھی جب اس کی میعاد گذر گئی اور آتھم نہ مرا تو ظاہربین لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی.ایک دفعہ نواب صاحب بہاولپور کے دربار میں بھی بعض لوگوں نے ہنسی اڑانی شروع کر دی کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اور آتھم ابھی تک زندہ ہے.اُس وقت دربار میں خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑاں والے بھی بیٹھے ہوئے تھے جن کے نواب صاحب مرید تھے.باتوںباتوں میں نواب صاحب کے مونہہ سے بھی یہ فقرہ نکل گیا کہ ہاں! میرزا صاحب کی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی.اس پر خواجہ غلام فرید صاحب جوش میں آگئے اور انہوں نے بڑے جلال سے فرمایا کہ کون کہتا ہے آتھم زندہ ہے مجھے تو اس کی لاش نظر آرہی ہے (اشارات فریدی جلد سوم صفحہ ۱۵)اس پر نواب صاحب خاموش ہو گئے.توبعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بظاہر زندہ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً مردہ ہوتے ہیں.اور بعض مردہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً زندہ ہوتے ہیں.جو لوگ خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں وہ درحقیقت زندہ ہوتے ہیں.اور جو لوگ زندہ ہوتے ہیں ان میں سے ہزاروں روحانی نگاہ رکھنے والوں کو مردہ دکھائی
Page 58
دیتے ہیں.کسی بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ قبرستان میں رہتے تھے ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ زندوں کو چھوڑ کر قبرستان میں کیوں آگئے ہیں.انہوں نے کہامجھے تو شہر میں سب مردے ہی مردے نظر آتے ہیں اور یہاں مجھے زندہ لوگ دکھائی دیتے ہیں(تذکرۃ الاولیاء از حضرت فرید الدین عطّار.ابراہیم ادھم).پس رُوحانی مردوں اور رُوحانی زندوں کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں.مگر اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری علامت ایسی بتا دی ہے جس سے روحانی مردوں اور زندوں کو پہچاننے میں بڑی حد تک آسانی ہوجاتی ہے.وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ.شعور وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے اندر کی طرف سے باہر کو آتا ہے.مثلاً اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے کوئی بات سن کر ایک نتیجہ قائم کرے تو وہ شعور نہیں کہلائے گا.وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے شعور حاصل کر لیا.بلکہ یہ کہے گا کہ مجھے علم ہو گیا.لیکن اگر اس کے نفس کے اندر سے وہ بات پیدا ہو تو وہ کہے گا مجھے فلاں بات کا شعور ہوا.چنانچہ جب ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ شعور کی عمر تک پہنچ گیا حالانکہ اس کو علم پہلے بھی حاصل ہوتا ہے.بالوں کو شعار اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اندر سے باہر کی طرف آتے ہیں اور شعار اس لباس کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے اور شعر کو بھی اسی لئے شعر کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ اندر سے باہر آتے ہیں اور اس کا مضمون ایسا ہوتا ہے جو انسان کے اندرونی احساسات کا ترجمان ہوتا ہے اور اُسے پڑھ کر انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بات تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہے.چنانچہ غالب اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ؎ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جواُس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ باتیں کہ شہداء کو ایک اعلیٰ درجہ کی حیات حاصل ہے.یا ایک ایک شہید کی جگہ لینے کے لئے پچاس پچاس اور سو سو آدمی آئیں گے یا وہ رنج و غم سے کلی طور پرآزاد ہیں.یا ان کے خون رائیگاں نہیں جائیں گے انسانی شعور سے تعلق رکھتی ہیں اگر کوئی شخص فطرتِ صحیحہ پر غور کرنے کا عادی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی.ماں جب تک اپنی جان کی قربانی پیش نہیں کرتی اُسے بچہ حاصل نہیں ہوتا.دانہ جب تک خاک میں مل کر اپنی جان کو نہیں کھوتا وہ ایک سے سات سو دانوں میں تبدیل نہیں ہوتا.اسی طرح کوئی قوم زندہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کے افراد جانوں کو ایک بے حقیقت شے سمجھ کر اُسے قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار نہ ہوں اور کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد کے دلوں میں اپنے شہداء کا پورا احترام نہ ہو.یہ ایک فطرتی آواز ہے جو شعور کے کانوں سے سنی جا سکتی ہے مگر جن لوگوں کو شعور حاصل نہیں.وہ بات بات پر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور جب بھی کسی مالی یا جانی قربانی کا مطالبہ کیا جائے ان کے قدم لڑکھڑانے
Page 59
لگ جاتے ہیں.اور وہ ان لوگوں کو بیو قوف سمجھتے ہیں جو اپنے آپ کو قربانیوں کی آگ میں جھونکنے کے لئے آگے نکل آتے ہیں.اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ تم اپنے شعور سے کام لو اور شہدا ء کو مردہ کہہ کر ان کی بے حرمتی مت کرو.وہ مردہ نہیں بلکہ حقیقتاً وہی زندہ ہیں.کیونکہ تاریخ ان کے نام کو زندہ رکھے گی اور آئندہ آنے والی نسلیں انہی کے نقشِ قدم پر چلیں گی اور ان کے کارناموں کو یاد رکھیں گی اورہمیشہ ان کی بلندی درجات اور مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور دُعائیں کرتی رہیں گی.تم اُسے زندہ سمجھتے ہو جو جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہو حالانکہ زندہ وہ ہے جس نے مرکر اپنی قوم کو زندہ کر دیا.اگر تمہیں شہداء بھی ُمردہ نظر آتے ہیں تو اس کے معنے یہ ہیں کہ تمہارا شعور ناقص ہے تم اس کی اصلاح کرو اور زندگی اور موت کے سلسلہ کو سمجھنے کی کوشش کرو.وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک(سے) اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعہ(سے) ضرور آزمائیں الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ١ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَۙ۰۰۱۵۶ گے اور (اے رسول!) تو (ان) صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے.حلّ لُغات.وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بَلَاءٌ کسی کے خیر اور شر کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں اور یہ ظاہر کرنا تین اغراض کے لئے ہوتا ہے.اول اپنا علم بڑھانے کے لئے جیسے اُستاد اپنے شاگرد کا اس غرض کے لئے امتحان لیتا ہے کہ اُسے معلوم ہو کہ طالب علم نے اپنا سبق یاد کیا ہے یا نہیں.دوم اس لئے کہ جس کو ابتلاء میں ڈالا گیا ہے اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی کیسی حالت ہے کیونکہ عام لوگ خود بھی نہیں جانتے کہ فلاں بات ہم میں ہے یا نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ منافقوں کے متعلق فرماتا ہے.وَمَایَخْدَعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَھُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ (البقرۃ:۱۰) یعنی منافق فسادی ہیں مگر وہ اس امر کو سمجھتے نہیں کہ ہم فساد کر رہے ہیں.سوم.اس لئے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص کی ایمانی حالت کیسی ہے؟ یہ مثال اعلیٰ درجہ کے لوگوں کی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم ؑسے سوال کیا تو اس کی غرض یہ تھی کہ فرشتوں کو معلوم ہو کہ آدم ؑ میں کیا کیا طاقتیں ہیں؟ خدا تعالیٰ چونکہ علیم و خبیر ہے اس لئے جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو پچھلے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے.نہ کہ پہلے میں.اگر ابتلاء نہ آئے تو انسان ایمان میں ترقی نہ کر سکے.اور اسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے ایمان کی کیا حالت ہے؟
Page 60
بَلَوْتُ الرَّجُلَ (بَلَاءً وَ بَلْوًا)وَابْتَلَیْتُہٗ کے معنے ہیں اِخْتَبَرْتُہٗ میں نے اس کا امتحان لیا اور اِبْتَلَاہُ اللہُ کے معنے ہیں اِمْتَحَنَہٗ اﷲ نے اس کا امتحان لیا.اور اس سے اِسْم اَلْبَلْوٰی.اَلْبَلْوَۃُ اَلْبَلِیَّۃُ اور اَلْبَلَاءُ آتا ہے یعنی امتحان.نیز لکھا ہے اَلْبَلَاءُ یَکُوْنُ فِی الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ کہ بلاء کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں.بلائے خیر بھی اور بلائے شر بھی.چنانچہ کہتے ہیں اِبْتَلَیْتُہٗ بَـلَاءً حَسَنًا وَّ بَلَاءً سَیِّئًا کہ میں نے اس کا اچھا امتحان لیا اور بُرا امتحان لیا.پھر لکھا ہے وَ اللہُ تَعَالٰی یَبْلِی الْعَبْدَ بَلَاءً حَسَنًا وَیَبْلِیْہِ بَلَاءً سَیِّئًا کہ اﷲ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان ہر دو طرح سے لیتا ہے بلائِ انعام سے بھی اور بلائِ تکلیف سے بھی.نیز اَلْبَـلَائُ کے معنے انعام کے بھی لکھے ہیں (لسان) اَلْبَلَاءُ کے اصل معنے امتحان کے ہوتے ہیں.لیکن امتحان چونکہ کبھی انعام کے ذریعہ سے اور کبھی سزا کے ذریعہ سے لیا جاتا ہے اس لئے بَلَاء کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں.انعام کا امتحان بھی اور تکلیف کا امتحان بھی.چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَبَلَوْنَاھُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّیِّئَاتِ (الاعراف :۱۶۹) ثَمَرَات اس کے معنے پھلوں کے بھی ہوتے ہیں اور کوششوں کے نتائج کے بھی.(اقرب) وَبَشِّرِالصّٰبِرِیْنَ بشارت ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے چہرہ پر اثر پڑے.خواہ وہ خوشی کی خبر ہو یا غم کی.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ قسم کے ابتلائوں کا ذکر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم ان ابتلائوں میں سے گذرے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے.ایک ابتلاء تو یہ ہو گا کہ دشمنوں کے حملوں کا خوف تمہیں لاحق ہو گا.ساری قومیں تمہارے خلاف کھڑی ہو جائیں گی.اور تم پر حملہ کریں گی.حکومتیں تم سے ناراض ہو جائیں گی.اور تمہیں مٹانے کی کوشش کریں گی.یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے بزدل لوگ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا جانے اب کیا ہو گا ؟اور بہت سے لوگوں کے حوصلے اس خوف کی وجہ سے پست ہو جاتے ہیں ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ پبلک اور حکومت نے ہمارے خلاف جتھہ بنا لیا ہے یا پنچائت نے ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے.پھر اس سے ترقی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے مومنوں کے ثباتِ قدم کا امتحان لیتا ہے.بھوک کی تکلیف سے یہ مراد ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے مامور کی آواز پر ایک گروہ جمع ہو جاتا ہے تو لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں.ملازمتوں سے برخواست کر دیتے ہیں.دوکانوں سے سودا نہیں دیتے.پیشہ وروں سے کام لینا بند کر دیتے ہیں گویا پہلے تو صرف دھمکیاں دیتے ہیں جن کی وجہ سے خوف لاحق ہوتا ہے کہ وہ کہیں نقصان نہ پہنچادیںمگر دوسرے قدم پر
Page 61
وہ عملی رنگ میںبھوک اور افلاس کے سامان پیدا کر دیتے ہیں مثلاً یہ کہ ان کو کوئی سودا نہیں دینا.ان کے پاس غلہ نہیں بیچنا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تو ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں روک لی گئیں اور یہ بائیکاٹ کا سلسلہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا (السیرۃالنبویۃ لابن ہشام، خبر الصحیفة).پھر فرماتا ہے کہ ان مصائب کا سلسلہ یہیں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تمہارے مالوں کا لُوٹنا بھی جائز قرار دے دیا جائے گا.گویا پہلے تو اپنے پاس سے مال واسباب اور سودا اور غلہ وغیرہ دینا بند کیا جائے گا اور پھر مومنوں کے پاس جو کچھ اندوختہ ہو گا اُسے بھی لُوٹنا جائز قرار دے دیا جائے گا.لیکن جب اس سے بھی کچھ نہیں بنتا تو پھر وہ مومنوں کی جانوں پر حملہ شروع کر دیتے ہیں.لیکن جب وہ جان دینے سے بھی باز نہیں آتے تو ان کی اولادوں پر حملے کرنے لگ جاتے ہیں.مَیں نے دیکھا ہے ہمارے سالانہ جلسہ کے موقعہ پر بعض خبیث الطبع لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو احمدیوں کے بچے اُٹھا کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ذریعہ سے جماعت کو دکھ پہنچائیں.اسی طرح ثمرات کے نقصان سے یہ بھی مراد ہے کہ دشمن ان کی کوششوں میں رخنہ ڈالیں گے اور انہیں مختلف قسم کے منافع سے محروم کرنے کی کوشش کریں گے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ادنیٰ درجہ کے مومنوں پر جو ابتلاء آتے ہیں وہ تو اس لئے آتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کی ایمانی حالت کیسی ہے؟ اور جو اعلیٰ درجہ کے مومنوں پر آتے ہیں وہ اس لئے آتے ہیں کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ ان کی کیا حالت ہے؟ عام طور پر لوگ اپنے متعلق خیال کرتے ہیں کہ انہیں ایمان میں ثباتِ قدم حاصل ہے مگر موقعہ آنے پر ان سے کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ یہ کمزوری ہے اور وہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.پھر ابتلاء آتا ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر فلاں نقص بھی موجود ہے اور وہ اُسے دُور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.اس طرح رفتہ رفتہ وہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں.لیکن اعلیٰ درجہ کے لوگوں پر اس لئے ابتلاء لائے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کیسے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی مصیبت ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کرتی.غرض بتایا کہ ہم تمہارے اندرونہ کو ظاہر کرنے کے لئے پانچ قسم کے ابتلاء تم پر وارد کریںگے.جن میں سے ایک خوف ہو گا جو بیرونی دکھ کا نام ہے.دوسرا ابتلاء بھوک کا ہوگا.جو اندرونی تکلیف ہے.گویا بعض کوبیرونی دکھوں اور تکالیف کے ذریعہ اور بعض کو اندرونی تکلیفوں کے ذریعہ سے ہم آزمائیں گے.بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑائی کے لئے تو تیار ہو جاتے ہیں مگر بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے.فوجوں میں سپاہی لڑتے ہیں مگر چونکہ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے اس لئے انہیں چنے وغیرہ دیئے جاتے
Page 62
ہیں.مگر مومن کی یہ حالت نہیں ہوتی وہ خدا کے لئے بھوکا رہنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓ کو باہر بھیجا تو ان میں سے کسی نے بھی یہ نہ پوچھا کہ ہم کھائیںگے کیا.چنانچہ وہ پتے کھا کر گذارہ کرتے تھے.اسی طرح ایک دفعہ انہوں نے کھجوروں کی گٹھلیاں کھا کر گذارہ کیا( نسائی کتاب الصید والذبائح باب میتة البحر).پس فرمایا ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ تم بہادر ہو یا نہیں اور یہ بھی کہ تم بھوک برداشت کرتے ہو یا نہیں.پھر بعض لوگ بھوک اور خوف تو برداشت کر لیتے ہیں مگر مال کے خطرہ کو برداشت نہیں کر سکتے.بعض مال کے خطرہ کو برداشت کر لیتے ہیں مگر جان کے خطرہ کو برداشت نہیں کر سکتے.پس فرماتا ہے تمہیں مالی اور جانی نقصانات بھی برداشت کرنے پڑیں گے اور بعض دفعہ اپنی کوششوں کے نتائج سے بھی محروم رہنا پڑے گا.ثمرات کے کم ہونے کی مثال اُحد کی جنگ ہے کہ وہ کفار سے لڑے بھی اور شہید بھی ہوئے مگر انہیں اس کا ثمرہ نہ ملا.اسی طرح ثمرات کے نقصان میں تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کی بربادی بھی شامل ہے.جو جنگ کا ایک لازمی نتیجہ ہوتی ہے غرض بتایا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو گا کہ تم کام کرو گے مگر اس کے فوائد تمہاری امیدوں کے مطابق نہیں نکلیںگے.مگر فرمایا وَبَشِّرِ الصّٰبِرِیْنَ.وہ لوگ جو ان تمام ابتلائوں کو برداشت کرلیں گے اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے.ان کو کوئی ڈر نہیں.وہ کہتے ہیں اگر لوگ ہمیں ڈراتے ہیں تو بے شک ڈرائیں.اگر ہمارا مقاطعہ کرتے ہیں تو بے شک کریں.اگر وہ ہمیں سودا سلف نہیںدیتے تو بے شک نہ دیںہم تو خدا تعالیٰ کے رستے میں قربانیاں کرتے چلے جائیں گے.اسی طرح اگر وہ ہمارے مال لُوٹنے پر آئے ہیں تو بے شک لُوٹ لیں اور پھر جب وہ ان کی جانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں توکہتے ہیں کہ تم ہمیں قتل کرکے بھی دیکھ لو اور جب وہ ان کی اولادوں پر حملہ کر کے ان کی تباہی کا سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا تم یہ کام بھی کر کے دیکھ لو.ہمیں تمہارے ان کاموں کی بھی پروا نہیں.غرض ابتداء سے انتہا تک وہ اُن کے ہر حملہ کے مقابلہ میں قائم رہتے ہیں اور یہی کہتے رہتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری مرضی ہے کر کے دیکھ لو.تم ہمیں صداقت سے منحرف نہیں کر سکتے.جب وہ پانچوں قسم کے ابتلائوں سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ ان میں ثابت قدم رہتے ہیں اور استقلال سے ان کو برداشت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ مبارک ہو! تمہارے ایمان کی پختگی ثابت ہو گئی.تم امتحان میں پاس ہو گئے اب تم اگلی جماعت کی تیاری کرو.صبر سے یہ مراد نہیں کہ انسان کو غم نہ ہو بلکہ صبر سے مراد یہ ہے کہ ایسا غم نہ ہو جس سے حواس جاتے رہیں اور عقل اور قوتِ عملیہ باطل ہو جائے.یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی فطرت انسانی کے مطابق تعلیم ہے.نہ غم سے روکا کہ وہ فطرتی امر
Page 63
ہے.نہ جزع فزع اور کام چھوڑ دینے کی اجازت دی کہ یہ بزدلی اور کم ہمتی کی علامت ہے.اس آیت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ میں قبلہ کی طرف منہ کرنے کا ذکر نہ تھا بلکہ فتح مکہ کا ذکر تھا.ورنہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مارے جانے اور ان ابتلائوں میں پڑنے کا کیا تعلق تھا.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس آیت میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ تم نے مکہ فتح کرنا ہے.مگر وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ میں بتایا کہ کام آسانی سے نہیں ہو گا بلکہ تمہیں سخت تکالیف میں سے گذرنا ہو گا.لیکن یہ تکالیف تمہارے لئے بہتر ہو ںگی کیونکہ ان سے تمہارے ایمانوں کی پختگی ظاہر ہو جائے گی.الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ١ۙ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ جن پر جب (بھی) کوئی مصیبت آئے (گھبراتے نہیں بلکہ یہ) کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَؕ۰۰۱۵۷ اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں.حلّ لُغات : مُصِیْبَۃٌ ہمارے ملک میں مصیبت ان تکلیف دہ واقعات کو کہتے ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں.لیکن عربی زبان میں مصیبت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو بہر حال پہنچنے والی ہو.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مشکلات سے بھاگتا اور ناپسندیدہ باتوں سے کنارہ کشی کرتا ہے.اور جو چیزیں اس کی خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہیں اُن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پس جس چیز کی طرف انسان خود بخود جائے وہ پہنچنے والی نہیں کہلاسکتی.لیکن جس سے انسان بھاگے اور وہ اُسے پکڑلے وہ پہنچنے والی کہلاتی ہے.اور چونکہ مصیبت سے ہر انسان بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی مصیبت اسے آچمٹتی ہے.اس لئے عربی زبان میں ایسی چیز کو جو انسان کا پیچھا نہ چھوڑے اور اس کے پاس پہنچ کر رہے مصیبت کہتے ہیں.لیکن اُردو میں خالص اس کے وہی معنے رہ گئے ہیں جو عربی میں ضمنی تھے اور مصیبت صرف اس بات کو کہتے ہیں جو تکلیف دہ ہو.تفسیر.اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزع فزع کرنے کی بجائے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اُسی کی طرف ہم لَوٹنے والے ہیں.یہ وہ نمونہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے امید رکھتا ہے.وہ چاہتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ گھبرانے
Page 64
اور جزع فزع کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اُسی کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے سچے دل سے یہ کہیں کہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ.بظاہر یہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے مگر اپنے اندر نہایت وسیع مطالب رکھتا ہے.(۱) اس فقرے میں دو جملے ہیں.ایک تو اِنَّا لِلّٰہِ ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں.اور دوسرا اِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَہے.یعنی ہم اُسی کی طرف لَوٹنے والے ہیں.پہلا جملہ اس مضمون پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی مالک اپنی چیز کو اپنے ہاتھوں تباہ نہیں کرتا بلکہ اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ مالک بڑا ہی بیوقوف ہوگا جو اپنی چیز کو آپ تباہ کرنے کی کوشش کرے.پس اگر بندہ محض خدا کا ہو جائے اور اُسی کو اپنا حقیقی مالک سمجھے تو اس کے دل میں یہ وہم بھی نہیں آسکتا ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے واپس لے لی ہے.یا وہ مصائب جو مجھ پر نازل ہو رہے ہیں ان میں میری تباہی اور بربادی مقصود ہے.جو مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور جس طرح ماں اپنے بچہ کو گود میں رکھتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے بھی مجھے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے وہ یہ تصور بھی کس طرح کر سکتا ہے کہ میں تباہ کیا جائوں گا اور میری تکالیف مجھ سے دور نہیں کی جائیں گی.محافظ کا تو فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو ہر نقصان سے بچائے پھر اللہ تعالیٰ جوتمام محافظوں سے بڑا محافظ ہے کب کسی مومن کو تباہ کر سکتا ہے.پس اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز اپنے بندے سے واپس لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ بہتر جگہ میں رکھتا ہے.اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے عورتیں اپنے گھروں کی صفائی کرتے وقت سامان وغیرہ کو ایک جگہ سے اُٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتی ہیں.تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ عورتیں اپنی چیزوں کو اِدھر اُدھر رکھیں تو وہ رونے لگ جائیں.یا مثلاً زمیندار کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیج کو ضائع کر رہا ہے مگر وہ روتا نہیں اس لئے کہ اس کا نتیجہ تباہی نہیں بلکہ ترقی ہوتا ہے.چنانچہ وہی بیج جب کچھ عرصہ کے بعد اُسے لہلہاتے ہوئے کھیتوں کی شکل میں واپس ملتا ہے تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں.اسی طرح بندہ اگر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرےگا اُس میں میری بہتری ہو گی تو کبھی بھی جزع فزع اور بے صبری کا اظہار نہ کرے.جب انسان ایک خوبصورت عمارت بناتا اور پہلی عمارت کو توڑتا پھوڑتا ہے تو اُس پر روتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے.اسی طرح اگر کپڑے کا دل اور اس کی آنکھیں ہوتیں تو جب درزی اُسے کاٹتا تو وہ رونے کی بجائے خوش ہوتا کہ یہ مجھے اچھا بنانے لگا ہے.یہی حال انسان کا ہے اگر انسان یہ یقین رکھے کہ خدا تعالیٰ میرا مالک ہے اور وہ جو تبدیلی بھی کرےگا میرے فائدہ کے لئے کرےگا تو وہ جزع فزع نہیں کر سکتا.ہاں غم کا اظہار کرنا صبر کے خلاف نہیں ہوتا.شادی کے وقت لڑکیاں اپنے گھروں کو رخصت ہوتی ہیں تو ماں باپ رونے لگ جاتے ہیں مگر یہ جزع فزع نہیں کہلاتا کیونکہ غم
Page 65
درحقیقت ایک قدرتی احساس ہے.جو مصیبت کے وقت ہر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے.اور اس کی علامت دل پر بوجھ ہونا اور آنکھوں میں آنسو آجانا ہے لیکن جزع فزع کرنے والا اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ خدا نے اُسے تباہ کر دیا ہے اور یہ چیز مومنانہ توکل اور ایمان کے بالکل خلاف ہے.پس اِنَّا لِلّٰہِ میںیہ بتایا گیا ہے کہ مصیبت یا ابتلاء کے آنے پر کافر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں مارا گیا لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بلا میں بھی میرے لئے کوئی خیر اور برکت کا پہلو پوشیدہ رکھا ہو گا.(۲) اِنَّا لِلّٰہِ کے دوسرے معنے یہ ہیں کہ مومن کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ جھٹ کہتا ہے کہ میرا تو اس چیز کے ساتھ صرف ایک عارضی تعلق تھا اصل تعلق تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اُسی کی خاطر اس چیز سے بھی میرا تعلق تھا اب اگر اُس نے اپنی کسی حکمت کے باعث یہ چاہا ہے کہ میرا اس چیز سے تعلق ٹوٹ جائے تو میں اس کے فعل پر کیوں اعتراض کروں؟ اس کی مثال حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی زندگی میں بھی ملتی ہے.ہمارا چھوٹا بھائی مبارک احمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا تھا.ماںباپ کو عموماً چھوٹے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں اس لحاظ سے حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کو اس سے بہت اُنس تھا اور پھر اس لئے بھی آپ اس سے زیادہ پیار کرتے تھے کہ وہ عموماً بیمار رہتا تھا.میری عمر جب وہ فوت ہوا اٹھارہ سال کے قریب تھی اس کی آخری بیماری کے ایام میں اس کا علاج کرنے میں بہت سے معالج مصروف تھے مثلاً حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ.ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب.ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب.حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس روز صبح کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو ساتھ ہی حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ اور ڈاکٹر صاحبان بھی آگئے.اس وقت اسے ضعف کی شکایت تھی لیکن چہرہ سے اچھی حالت معلوم ہوتی تھی ڈاکٹروں نے اُسے دیکھ کر کہا کہ اب افاقہ معلوم ہوتا ہے.اور وہ مطمئن ہو گئے لیکن حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ چونکہ زیادہ تجربہ کار تھے اس لئے آپ نے فوراً معلوم کر لیا کہ بچہ کی حالت نازک ہے.انہو ں نے گھبرا کر فورا ً نبض دیکھنی شروع کر دی.لیکن نبض کی حرکت معلوم نہ ہوئی.کیونکہ جوں جوں انسان موت کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کی نبض پیچھے ہٹنی شروع ہو جاتی ہے.پھر آپ نے اس کی بغل میں ہاتھ رکھا وہاں بھی نبض نہ ملی.جب حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبض نہیںملتی تو آپ نے گھبرا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور جلدی مشک دیجیئے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام ٹرنک میں سے مشک نکالنے کے لئے تشریف لے گئے تو چونکہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبارک احمد سے بہت پیار رکھتے ہیں اس لئے آپ نے جب دیکھا کہ مبارک احمد فوت
Page 66
ہو رہا ہے تو آپ کو اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ آپ کھڑے بھی نہ رہ سکے.زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا حضور جلدی مشک لائیے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس فقرہ سے سمجھ گئے کہ بچے کی حالت اچھی نہیں اور ویسے ہی بغیر مشک لئے واپس آگئے.اور فرمایا کیا بچہ فوت ہو گیا ہے؟ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا.ہاں حضور فوت ہو گیا ہے.آپ نے فوراً اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ پڑھا.اور بجائے کسی گھبراہٹ کا اظہار کرنے کے باہر کے احمدیوں کو خط لکھنے شروع کر دیئے کہ مومنوں پر ابتلاء آیا ہی کرتے ہیں.ان سے گھبرانا نہیں چاہیے.بلکہ اپنے ایمان کو پختہ رکھنا چاہیے اور پھر لکھاکہ مبارک احمد کی وفات کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مجھے خبر دے دی تھی کہ یہ چھوٹی عمر میں ہی اُٹھا لیا جائے گا.پس اس کے فوت ہونے سے خدا تعالیٰ کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے.پھر آپ نے اس کے کتبہ کے لئے جو اشعار لکھے.اُن میں سے ایک یہ بھی مصرع ہے کہ ع بُلانے والا ہے سب سے پیارا اُسی پہ اے دل تو جاں فد اکر یہ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ کا ہی ایک رنگ میں مفہوم رکھتاہے.غرض مومن کو جب کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو خدا سے تعلق ہے اگر میرے کسی عزیز کو خدا تعالیٰ نے اپنے پاس بُلا لینا مناسب سمجھا ہے تو مجھے اس پر کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ اُسی کی چیز تھی اور وہی بلانے کا حق دار تھا پس.اِنَّا لِلّٰہِکے ایک تو یہ معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تباہ نہیں کرےگا اور دوسرے معنے یہ ہیں کہ ہمارا تعلق صرف خدا کی وجہ سے ہے پس جس بات میں ہمارا خدا راضی ہے اس میں ہم بھی راضی ہیں.(۳) تیسری بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اَنَا لِلّٰہِ نہیں فرمایا بلکہ اِنَّا لِلّٰہِ فرمایا ہے تاکہ یہ اقرار صرف انفرادی رنگ میں نہ ہو بلکہ ہرانسان علیٰ وجہ البصیرت اس یقین پر قائم ہو کہ دنیا کی ہرچیز خدا تعالیٰ کی ہے اور ہمارا ان سے محض عارضی تعلق ہے.پس نہ صرف مجھے بلکہ دنیا کے کسی انسان کوبھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کرے یا اس کی کسی تلخ قاش پر اپنا مونہہ بنانا شروع کر دے.مثنوی رومی ؒ میں حضرت لقمانؓ کے متعلق جن کو بعض لوگ نبی بھی سمجھتے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ انہیں کسی نے ان کے والدین کی وفات کی وجہ سے غلام بنا لیا اور ایک تاجر کے پاس بیچ دیا.اس تاجر نے انہیں ذہین اور ہوشیار سمجھ کر ان سے غلاموں والا سلوک ترک کر دیا اور اُن سے محبت کرنے لگا.ایک دن کسی نے اس کو تحفۃً ایک خربوزہ پیش کیا جو بظاہر بہت اچھا تھا.اس نے ایک قاش کاٹ کر حضرت لقمان کو دی.انہوں نے چکھی تو نہایت
Page 67
کڑوی تھی لیکن بڑے مزے لے لے کر کھانی شروع کر دی.مالک نے ایک اور قاش کاٹ کر دے دی.حضرت لقمان نے پھر مزے لے لے کر کھائی.حتّٰی کہ تاجر نے یہ سمجھ کر کہ یہ بڑا میٹھا خربوزہ ہے ایک قاش خود بھی چکھی تو اسے معلوم ہوا کہ نہایت کڑوا خربوزہ ہے.اس پر وہ حضرت لقمان کو خفا ہوا کہ تم نے بتایا کیوںنہیں.اگر تم بتا تے تو میں تمہیں اور کڑوی قاشیں تو نہ کھلاتا.حضرت لقمان نے کہا کہ جس ہاتھ سے اتنی میٹھی قاشیں مَیں نے کھائی ہوئی تھیں کیا میں اتنا ہی بے شرم تھا کہ اس کی ایک دو قاشوں کو کڑوی سمجھ کر ردّ کر دیتا.تواِنَّالِلّٰہِ کا بھی یہی مفہوم ہےکہ وہ خدا جس نے ہمیں اتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں اگر اس نے کسی حکمت کے ماتحت ایک نعمت واپس لے لی ہے یا ہزاروں خوشیوں کے ہوتے ہوئے ایک مصیبت ہم پر آگئی ہے تو کیا ہوا سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے.اگر وہ اپنی مرضی سے ایک چیز واپس لے لیتا ہے تو اس پر جزع فزع کرنے سے زیادہ اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ (۴) چوتھے معنے جو اس سے زیادہ اعلیٰ اور مومن کے مقام کے مطابق ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ صرف سب کی سب نعمتیں اُسی کی ہیں اور وہی اس کا حقیقی مالک ہے اگر ایک نعمت اس نے واپس لے لی تو کیا ہوا؟ بلکہ ہمارے پاس جو کچھ باقی ہے اگر وہ بھی ہم سے لے لینا چاہے تو ہم باقی چیزیں بھی اس کی راہ میں دینے کے لئے تیار ہیں.چنانچہ صحابہؓ کرام میں اس کی بہت سے مثالیں ملتی ہیں.حضر ت عثمان بن مظعونؓ ایک بڑے مخلص صحابی تھے اور مکی زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد جب آپؐ کے بیٹے حضرت ابراہیم ؓ فوت ہوئے تو آپؐ نے انہیں فرمایا کہ جا اپنے بھائی عثمان بن مظعونؓ کے پاس (الاستیعاب باب حرف العین).گویا ان کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا قرار دیا.وہ کسی رئیس کے بیٹے تھے.ان کے والد فوت ہو گئے تو ان کے باپ کے کسی دوست نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اعلان کر دیا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے کوئی شخص اسے تکلیف نہ دے.چند دن تو وہ آزادانہ طور پر پھرتے رہے اور انہیں کسی نے کوئی تکلیف نہ دی لیکن ایک دن انہوں نے دیکھا کہ بعض کمزور مسلمانوں اور غلاموں کو کفار سخت تکلیف دے رہے ہیں اور انہیں تپتی ریت پر لٹا کر دکھ دے رہے ہیں ان سے یہ نظارہ برداشت نہ ہو سکا اور فوراً گھر آکر اُس رئیس سے کہا کہ چچا مہربانی کر کے اپنی پناہ واپس لے لو.میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ دوسرے مسلمانوں کو تو لوگ سخت سے سخت سزائیں دیں اور میں مزے سے اِدھراُدھر پھروں.چنانچہ اُس رئیس نے اپنی پناہ کا اعلان منسوخ کر دیا.اسی اثناء میں لبید جو ایک بہت بڑا شاعر تھا(اور جو بعد میںمسلمان بھی ہو گیا) وہ مکہ میں آیا اور لوگوں نے اس کے اعزاز میں ایک مجلس مشاعرہ قائم کی.حضرت عثمان بن مظعونؓ اور وہ ریئس بھی وہیں تھے.اکثر شعراء نے
Page 68
اپنے اپنے شعر پڑھے.پھر لبید کی باری آئی تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اَ لَا کُلُّ شَیْءٍ مَا خَلَا اللّٰہَ بَاطِلُ یعنی سُنو! کہ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کے سوا فنا ہونے والی ہے ابھی انہوں نے یہ مصرع پڑھا ہی تھا کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ بول اُٹھے کہ خوب کہا ٹھیک کہا.اس پر لبید کو غصہ آیا کہ کیا میں اتنا ہی حقیر ہوں کہ اس چھوٹے سے بچے کی تصدیق کا محتاج ہوں.اور اس نے اہل مجلس کو غیرت دلائی کہ یہ کیا بدتہذیبی ہے جو تم لوگوں نے اختیار کر لی ہے کہ ایک بچہ مجھے داد دیتا ہے.چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کو ڈانٹا اور کہا کہ خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا.اس کے بعد انہوں نے دوسرا مصرع پڑھا ع وَکُلُّ نَعِیْمٍ لَا مَحَا لَۃَ زَائِلٗ یعنی ہر نعمت ایک دن زائل ہونے والی ہے.اس پر حضرت عثمان بن مظعون پھر بول اُٹھے اور کہنے لگے.یہ درست نہیں جنت کی نعمتیں کبھی زائل نہیں ہوںگی.لبید کو سخت غصہ آیا اور اس نے پھر لوگوں کو غیرت دلائی کہ تم نے میری بے عزتی کی ہے.اب میں کوئی شعر نہیں پڑھوں گا.اس پر ایک شخص کو اتنا جوش آیا کہ اس نے اُٹھ کر حضر ت عثمان بن مظعونؓ کے منہ پر ایک مکا مارا جس کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ نکل گئی.ان کے وہ ہمدرد رئیس جنہوں نے ان کو پناہ دے رکھی تھی وہ بھی وہیں پاس بیٹھے تھے.چونکہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ دوسروں کے مقابلہ میں کھڑے ہو سکیں اس لئے انہوں نے حضرت عثمان بن مظعونؓ کو ہی ڈانٹنا شروع کر دیا.اور جس طرح کسی غریب عورت کے بچے کو کوئی امیر آدمی کا بچہ مار جائے تو وہ اپنے بچے کو ہی ڈانٹتی ہے اور کہتی ہے کہ تو گھر سے کیوں باہر نکلا تھا.اسی طرح انہوں نے بھی حضرت عثمان بن مظعونؓ کو ڈانٹنا شروع کیا کہ تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ میری پناہ سے نہ نکلو.اب دیکھا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس پر حضرت عثمان بن مظعونؓ نے جواب میں کہا چچا! آپ کو تو میری ایک آنکھ کے نکلنے کا افسوس ہے اور میری تو دوسری آنکھ بھی خدا تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لئے تیار ہے(اسد الغابۃ ذکر عثمان بن مظعون).تو حقیقی مومن قربانی سے گھبراتا نہیں بلکہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کی کوئی قیمتی متاع ضائع ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مرنے والا اور باقی رہنے والے سب اس کے ہی ہیں.پس اگر وہ اللہ کی چیز تھی اورہم بھی اسی کے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے ایک غلام کے پاس رکھوائی ہوئی امانت واپس لے گیا تو اسے شکوہ کا کیا حق ہے.میں تو سب کچھ اس کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہوں.(۵) مگر یہ پہلا حصہ کچھ استغناء ظاہر کرتا ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر دوسرا حصہ اس
Page 69
کے ساتھ لگادیا کہ اِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ اور اس طرح اس تعزیت کو مکمل فرما دیا.پہلے فرمایا تھا کہ اگر ہم تم کو کوئی انعام دیتے ہیں اور پھر وہ انعام تم سے لے لیتے ہیں تو تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے.کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے محسن نے فلاں چیز مجھے دی تھی اور میں اس سے پانچ سال یا دس سال یا بیس سال یا تیس سال یا چالیس سال یا پچاس سال تک فائدہ اٹھاتا رہا اس کے بعد وہ اپنی امانت مجھ سے کیوں لے گیا؟ اس بات پر اُسے شکوے کا کیا حق ہے؟ یہ تو اس کا احسان تھا کہ جتنی مدت وہ چیز اس کے پاس رہی اس سے وہ پوری طرح فائدہ اُٹھاتا رہا.اب اس کے بعد فرماتا ہے کہ یاد رکھو اگر تمہارا کوئی عزیز ہم نے تم سے جُدا کر دیا ہے تو مومن کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ دنیا سے کسی کااُٹھ جانا دائمی جُدائی کا موجب تو نہیں ہوتا.اگر یہ دائمی جُدائی ہوتی اور فرض کرو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی.تب بھی کیا خدا کا حق نہیں تھا کہ جو چیز اُس نے دی ہے وہ اُسے واپس لے لے؟ لیکن وہ زائد وعدہ یہ کرتا ہے کہ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ.ایک شخص اگر خدا کی طرف گیا ہے تو ہم بھی ایک دن اُسی کی طرف چلے جائیں گے.فرق صرف یہ ہے کہ کسی نے پہلے سفر طے کر لیا اور کوئی بعد میں سفر کے لئے چل پڑےگا ورنہ منزل مقصود سب کی ایک ہی ہے اور جب منزل مقصود ایک ہی ہے تو اس میں گھبراہٹ کی کونسی بات ہے؟ بچے بعض دفعہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ولایت بھیج دیئے جاتے ہیں.اب کسی کی زندگی کا کیا اعتبار ہوتاہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک یا دو دن بھی اور زندہ رہےگا.نہ والدین جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنا عرصہ زندہ رہنا ہے نہ لڑکے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کب تک ہے؟ مگر باوجود اس کے جب لڑکوں کو پڑھنے کے لئے ولایت بھیجا جاتا ہے تو پانچ پانچ چھ چھ دس دس سال تک مائیں صبر کرتی ہیں باپ صبر کرتے ہیں اور وہ گھبراہٹ سے کام نہیں لیتے.کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آخر ہمارے بچے ایک دن آجائیںگے.یا اگر کسی سفر پر کوئی شخص پہلے چل پڑتا ہے اور دوسروں نے بھی وہیں جانا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند دن کے بعد اُس سے جا ملیں گے.جانا تو ہے ہی.تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے یہ اقرار کرو کہ خدا نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اس کے شکر گذار ہیں پھر یہ بھی سمجھ لو کہ تم سارے ایک دن خدا کے پاس جمع ہونے والے ہو اور اس کے پاس پہنچ کر اکٹھے ہو جائو گے.پس فرماتا ہے جب تم سارے ایک دن اکٹھے ہونے والے ہوتو خدا کے فعل پر شکوہ یاجزع فزع کتنی بڑی نادانی ہے.اگر تم جزع فزع کر وگے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہارا اپنے عزیزوں سے آخری اتصال کمزور ہو جائے گا کیونکہ جس خدا کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اگلے جہان میں سب کو اکٹھا کر دے اس کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ وہ اگلے جہان میں بعض کو جُدا جُدا رکھے.پس مومن کی اصل تعزیت اِنَّالِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہی ہے.باقی جہاں تک جسم کا تعلق ہے جسم جب کٹتا ہے تو ضرور دکھ پاتا ہے.صحابہؓ جنگوں میں شہید ہوئے اور اپنی خوشی
Page 70
سے شہید ہوئے.لیکن جہاں تک جسم کے کٹنے کا سوال ہے ان کو ضرور تکلیف ہوئی پس جسم بے شک دُکھ پاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اُس بندے پر جس کی رُوح خدا کے آستانہ پر جُھکی رہے اور اس سے کہے کہ اے میرے رب! مجھے کوئی شکوہ نہیں تُو نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا.یہی عین مصلحت تھی اور یہی چیز میرے لئے بہتر تھی.تیرا فعل بالکل درست ہے اور گو مجھے سمجھ میں نہ آئے مگر میں یہی کہتا ہوں کہ تیرا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں.(۶) پھر اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ میں ایک اور مضمون بھی بیان کیا گیا ہے.اور وہ یہ کہ جب کوئی رنج انسان کو پہنچتا ہے.تو فطرت کہتی ہے کہ میرے اندر آخر کوئی کمزوری تھی.تبھی تو مجھے یہ دُکھ پہنچا.اگر میں طاقتور ہوتا تو یہ دُکھ کیوں پہنچتا.اب اس دُکھ کو کوئی طاقتور ہی دُور کر سکتا ہے.غرض رنج ہمیشہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت مد د کرے.اور جب انسانی ذہن کو فطرت اس طرف لے جاتی ہے کہ اب کوئی غیر طاقت ہی مدد کرے تو معاً اس کا دل اِدھر مائل ہوتا ہے.کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو اس دُکھ کو دُور کرے.چنانچہ اُس وقت وہ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی ہوں اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں اس کے سوااور کون ہو سکتا ہے جو میری مدد کرے؟اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کے بے شک یہ بھی معنے ہیں کہ آخر ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے لیکن اس کے یہ معنے بھی ہیں کہ اگر ہم نے لَوٹنا ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف لَوٹنا ہے.اگرہم نے گریہ وزاری کرنی ہے تو اس کے سامنے ہی کرنی ہے.پس اسلام نے یہ سبق فطرت کے تقاضا کے عین مطابق دیا ہے جب کوئی رنج پہنچتا ہے تو یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے اس لئے وہ اُسے خود دُور نہیں کر سکتا.وہ طبعاً یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے دوست اور عزیز اس کی مدد کریں.مگر فرمایا یاد رکھو تمہارا سب سے بڑاعزیز اور دوست خدا تعالیٰ ہے.تم اس کے سامنے جھکو اور اس سے مدد طلب کرو.جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سبق پر عمل کرتے ہیں وہ ناکام و نامراد نہیں رہتے.ناکام و نامراد وہی ہوتا ہے جو غیرطبعی فعل کرتا ہے.مثلاً رات کو ڈاکہ پڑتا ہے تو عقلمند شخص اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے مدد طلب کرتا ہے لیکن بیوقوف انسان دوڑ کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے حالانکہ جنگل میں اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا.اسی طرح روحانی دنیا میں ایک عقلمند انسان تو خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے لیکن بیوقوف یو نہی ہائے اماں ہائے اماں! کہتا رہتا ہے.اب صاف ظاہر ہے کہ اماں نے کیا کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے خدا تعالیٰ نے ہی کرنا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے پاس جاتا نہیں.وہ اس کے پاس جاتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا.پس انسان کا فرض ہے کہ جب اُسے کوئی رنج پہنچے تو وہ فوراًاِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کہے.یعنی اگر مجھ پر مصیبت آگئی ہے تو بقول پنجابی بزرگوں کے ’’مُلّا کی دوڑ مسیت تک‘‘ میں نے تو خدا تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور
Page 71
اس سے مدد طلب کرنی ہے اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے اپنی برکات سے حصہ دیتا اور اس کے مصائب کو دور فرما دیتا ہے.(۷)اسی طرح وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ میں یہ لطیف مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے غلام ہیں اور اُسی کی طرف لَوٹنے والے ہیں.پس اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس صدمہ کا بہتر بدلہ مل جائے گا.پھر ہمیں کسی جزع فزع کی کیا ضرورت ہے؟ گھبراہٹ صرف اسے ہو سکتی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ دُکھوں اور تکالیف کے بدلہ میں کوئی جزا مقدر نہیں.مگر مومن تو سمجھتے ہیں کہ جب ہم خدا تعالیٰ کے پاس جائیںگے تو وہ ہمارے دکھوں کا بدلہ اپنے غیر معمولی انعامات کی شکل میں ہمیں عطا فرمائےگا.اور جب کوئی ایمان اور یقین کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو تو اسے بے صبری دکھانے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صابرین کی تعریف فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ ہمارے نزدیک کون لوگ صابر ہیں.اسلام کے نزدیک صابرین کی یہ تعریف ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی توجہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ ایک بچہ جب ماں کی گود میں ہوتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا.اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی گود میں سمجھتے ہیں اس لئے کسی مصیبت کے آنے پر مایوس نہیں ہوتے.اور اگر صبر کے معنے بدی سے رُکنے کے سمجھے جائیں تو پھر اس آیت کے یہ معنے ہوںگے کہ جب اُن پر کوئی ایسی تکلیف آتی ہے جس سے انسان بدی کی طرف مائل ہو تا ہے.جیسے قحط ہے کہ اس میں لوگ چوریاں وغیرہ کرنے لگ جاتے ہیں.تب بھی وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اگر صبر سے مراد نیکی پر قائم رہنا ہو تو اس کے یہ معنے ہوںگے کہ جب کوئی شیطانی تحریک انہیں نیکی سے منحرف کر نا چاہے تو اس وقت بھی وہ فوراً خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور اسی سے اپنے روحانی پیوند کا اظہار کرتے ہیں.غرض یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے مگر اپنے اندر بڑے وسیع مطالب رکھتا ہے.اور جو لوگ صاحب حال ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس فقرہ کے کہنے سے جن تکالیف کا ازالہ ممکن ہو اُن کا تو ازالہ ہو جاتا ہے اور جن کا ازالہ ناممکن ہو ان کا نسان کو کسی اور رنگ میں بدلہ مل جاتا ہے.مثلاً اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ مردے اس دنیا میں واپس نہیں آتے.پس اگر کوئی شخص مرجاتا ہے تو اس سنت اور فیصلہ کے ماتحت وہ زندہ ہو کر اس دنیا میں واپس نہیں آسکتا.لیکن اگر یہ فقرہ پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کہا جائے تو کہنے والے کو کسی نہ کسی رنگ میں اس کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے.اور اگر انسان کا کوئی ایسا نقصان ہو جائے جس کا بدلہ ملنا ممکن ہو مگر وہ پھر بھی نہ ملے تو اس کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ
Page 72
اللہ تعالیٰ کی تقدیر خاص اس میں روک بن رہی ہے ورنہ اس کا بدلہ ضرور مل جاتا.اُولٰٓىِٕكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ١۫ وَ اُولٰٓىِٕكَ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں (نازل ہوتی )ہیں اور رحمت (بھی) هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ۰۰۱۵۸ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.حل لغات.صَلٰوۃٌ جیسا کہ اوپر حل لغات میں بتایا جا چکا ہے صَلٰوۃٌ کے کئی معنے ہیں.مگر جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنے صرف مغفرت اور حسنِ ثناء کے ہوتے ہیں.عبادت کے معنے اس لئے چسپاں نہیں ہو سکتے کہ عبادت خدا تعالیٰ کی کی جاتی ہے اس کی طرف سے آتی نہیں.اسی طرح رحمت کے معنے بھی یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے.کیونکہ صَلٰوۃ کے ساتھ ہی رحمت کا لفظ بھی آگیا ہے.پس اس جگہ اس کے معنے صرف یہ ہیں کہ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مغفرت حاصل ہو گی یا انہیں ثنائے جمیل عطا کی جائےگی.تفسیر.اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ارضی اور سماوی آفات پر سچے دل سے اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مغفرت سے حصہ دیتا ہے یعنی وہ ان کے نقصانات کا ازالہ کرتا اور ان کی ناکامی کو کامیابی میں اور تکلیف کو راحت میں بدل دیتا ہے.اسی طرح اُن پر اللہ تعالیٰ کا فضل حسن ثناء کی صورت میں نازل ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی نیک شہرت دنیا میں قائم کر دیتا ہے اور لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر خیر جاری ہو جاتا ہے.چنانچہ دیکھ لو! مسلمانوں نے اسلام کی اشاعت کے لئے کتنی بڑی قربانیوں سے کام لیا تھا.انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں اور اولادوں کو بلا دریغ قربان کر دیا اور کسی بڑی سے بڑی مصیبت کی بھی پرواہ نہ کی.اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دشمنانِ اسلام تک بھی ان کی تعریف کئے بغیر نہیں رہ سکتے.وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں مگر جب صحابہؓ کی قربانیوں کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کے لئے جو نمونہ دکھایا وہ یقیناً بے مثال تھا.ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر آتی ہے کہ ہمیں چند آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں جس پرکھجور کی شاخوں کی چھت پڑی ہوئی تھی اور جو ذرا سی بارش سے بھی ٹپکنے لگ جاتی تھی آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے دکھائی دیتے ہیں.اور جب ہم ان
Page 73
کے قریب پہنچ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں کیاباتیں کر رہے ہیں؟تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم قیصر و کسریٰ کو کس طرح شکست دیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر اندر واقعہ میں ایسا ہی ہو گیا.اور ان بے سرو سامان اور کمزور درویشوں نے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو پاش پاش کر دیا.غرض اشد ترین دشمنوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی تھی اور وہ ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے.یہاں صلٰوۃ اور رحمۃ کو اکٹھا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ دنیا میںحکومتوں کی طرف سے عزت افزائی کے دو ہی طریق مقرر ہیں.یا تو کوئی خاص اعزاز بخشا جاتا ہے یا مادی رنگ میں کوئی انعام دیا جاتا ہے جیسے اعزازی طور پر لوگوں کو خطابات دیئے جاتے ہیں اور مادی طور پر انہیں مربعے وغیرہ دیئے جاتے ہیں.مگر گورنمنٹ کے خطابات تو بے حقیقت ہوتے ہیں.بعض دفعہ وہ ایک ایسے شخص کو خان بہادر کا خطاب دے دیتی ہے جو بزدل ہوتا ہے اور چوہے سے بھی ڈر جاتا ہے.مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے جسے کوئی خطاب دیا جاتا ہے وہ اس کا سچ مچ اہل ہوتا ہے.مگر افسوس ہے کہ لوگ دونوں طرف دھوکا کھا جاتے ہیں.وہ گورنمنٹ کے خان بہادروں کو واقعی خان بہادر سمجھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے خان بہادروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے حالانکہ جب خدا تعالیٰ کسی کو کوئی خطاب دیتا ہے تو اس کے اوصاف بھی اس میں پیدا کر دیتا ہے.حضرت مسیح موعو د علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص جو احمدی تھا مگر اس کے دماغ میں کچھ نقص تھا قادیان آیا.اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے الہام ہوتا ہے کہ تو محمد ہے تو موسیٰ ہے تو عیسیٰ ہے.آپ نے فرمایاکیا اس کے بعد تمہیں وہ کچھ ملتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا.وہ کہنے لگا ملتا تو کچھ نہیں آپ نے فرمایا پھر یہ شیطانی الہام ہے.کیونکہ خدا تعالیٰ تو یہ تمسخر نہیں کرتا کہ کسی کو کوئی خطاب دے اور اس کے اوصاف اس میں پیدا نہ کرے.خدا تعالیٰ تو جب کسی کو کوئی خطاب بخشتا ہے تو اس کے مطابق اُسے طاقتیں بھی دےدیتا ہے.یہ شیطان ہے جو تمہیں دیتا تو کچھ نہیں مگر تمہارا نام موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رکھتا چلا جاتا ہے.غرض صلوٰۃ کا تعلق روحانی انعامات سے ہوتا ہے اور رحمت کا تعلق ان مادی انعامات سے ہوتا ہے جو ماحول سے تعلق رکھتے ہیں.پس بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنّت ہے کہ وہ ابتلائوں میں ثابت قدم رہنے والوں کو روحانی برکات سے بھی مستفیض کرتا ہے اور انہیں مادی فوائد اور ترقیات جو ماحول سے تعلق رکھتی ہیں وہ بھی عطا کرتاہے.وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.اس جگہ ہدایت سے مراد صرف صراطِ مستقیم پر چلنا نہیں کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہدایت یافتہ
Page 74
اور صراطِ مستقیم پر قائم ہوتے ہیں.یہاں یہ معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستہ پر لئے جائے گا اور وہ اپنے اخلاص اور ایمان میں آگے ہی آگے بڑھتے جائیںگے.دوسرے معنے یہ ہیں کہ مشکلات اور مصائب میں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستہ بتاتا جائےگا اور مشکلات کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی انہیں نظر آتا جائےگا.تیسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ بندہ جب سچے دل سے اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کہتا ہے اور مصائب پر صبر سے کام لیتا ہے تو مومن کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی عرش پر بیتاب ہو جاتا ہے.اور وہ اس محبت اور اخلاص کی جزا دینے کے لئے اُسے اپنی ہدایت کی راہوں پر چلاتے ہوئے منزلِ مقصود پر پہنچا دیتاہے.گویا صبر اور استقامت کے نتیجہ میں وہ منعم علیہ گروہ میں شامل ہو جاتا ہے اور وصلِ الہٰی کے دروازے اس پر کھول دیئے جاتے ہیں.غرض تین قسم کے انعامات کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے.(۱)اول ہدایت کی راہوں میں ترقی(۲) دوم مشکلات میں صحیح راہنمائی(۳) سوم خدا تعالیٰ کا دائمی وصال.اور جن کو یہ فوائد حاصل ہوں ان کو اپنے کسی عارضی نقصان کا خیال بھی کس طرح آسکتا ہے.اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ١ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ صفا اور مروہ یقیناً اللہ (تعالیٰ) کے نشانات میں سے ہیں.سو جو شخص اس گھر (یعنی کعبہ) کا حج یا اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا١ؕ وَ مَنْ تَطَوَّعَ عمرہ کرے تو اسے اِن کے درمیان تیز چلنے پر کوئی گناہ نہیں.اور جو شخص خوشی سے کوئی نیک کام کرے(وہ سمجھ لے کہ) خَيْرًا١ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ۰۰۱۵۹ اللہ (نیک کاموںکا) قدردان ہے(اور وہ) بہت جاننے والا ہے.حلّ لُغات.صَفَا صَفَاۃٌ کی جمع ہے اور اس کے معنے ہیں سخت موٹے پتھر جن پر مٹی نہ ہو.اور کھیتی بھی نہ ہو سکے.صفا بیت اللہ کے پاس بڑے بڑے پتھروں کی ایک پہاڑی کا بھی نام ہے.(اقرب) اَلْمَرْوَۃَ یہ مَرْوٌ کا مفرد ہے اور مروہ ان سفید چھوٹے چھوٹے چمکتے ہوئے چقماقی صفت رکھنے والے
Page 75
پتھروں کو کہتے ہیں جن سے لوگ آگ نکالتے ہیں.مروہ بھی ایک پہاڑی کانام ہے جو بیت اللہ کے پاس ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنی ہوئی ہے.غرض صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا نام ہے جو خانہ کعبہ کے پاس ہیں.اور اب خانہ کعبہ وسیع ہو کر اُن کو آ لگا ہے اور ایک دروازہ ان میں آکر کھلتا ہے ان پر ایک بازار ہے جو سوقِ صفا کہلاتا ہے اور شہر کا حصہ ہے اور اسی بازار میں اب سعی ہوتی ہے پہلے دونوں پہاڑیاں الگ الگ تھیں لیکن اب بھرتی پڑ کر مل گئی ہیں اور ایک ہی معلوم ہوتی ہیں صرف دو نشان لوگوں نے سعی کے لئے بنا رکھے ہیں جن سے سعی شروع کرنے اور ختم کرنے کا حال انسان کو معلوم ہوتا ہے.(اقرب) شَعَائِرـ شَعِیْرَۃٌ کی جمع ہے اس کے معنے علامت آیت اور نشان کے ہوتے ہیں اور عبادات کے مقررہ طریقوں کو بھی شعیرۃ کہتے ہیں.یہاں علامت کے معنی مراد ہیں.حَجَّ حج کے اصل معنے قصد کے ہیں مگر اصطلاح شریعت میں اس کے معنے ذوالحجہ میں بیت اللہ جانے اور وہاں خاص احکام بجالانے کے ہیں.اِعْتَمَرَ اِعْتَمَرَالْمَکَانَ کے معنے ہوتے ہیں قَصَدَہٗ وَ زَارَہٗ.کسی بزرگی رکھنے والے مکان کی طرف جانے کا قصد کیا.اور اس کی زیارت کی.اسی طرح کہتے ہیں اِتَّخَذْ نَا نَادِیًا نَعْتَمِرُہٗ.کہ ہم نے ایک ایسی مجلس قائم کی ہے جس میں ہم بار بار جاتے ہیں اور ہماری آپس میں ملاقات ہوتی ہے پس اعتمار کے اصل معنے کسی شہر کی زیارت یا کسی ایسے مکان کی طرف جانے کے ہیں جو اپنی بزرگی یا دوستوں کی ملاقات کے لحاظ سے قابلِ اعزاز ہو.لیکن شریعت میں طواف بیت اللہ اور صفا اور مروہ کی سعی کا نام ہے.اور یہ عبادت سال کے ہر حصہ میں ہو سکتی ہے لیکن حج کا ایک خاص وقت مقرر ہے اسی طرح حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ عمرہ میں وہیں سے احرام باندھ لیتے اور سر منڈا لیتے ہیں.لیکن حج میں مقررہ جگہوں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے.جُنَاحٌ جَنَحَ کے معنے ہوتے ہیں مَالَ یعنی جُھک گیا.پروں کو بھی اور بازوئوں کوبھی اسی لئے جناح کہتے ہیں اور گناہ کو بھی جناح اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں انسان بدی کی طرف جُھک جاتا ہے.گناہ کا لفظ دراصل جناح کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے.یَطَّوَّفَ طَوَّفَ حَوْلَ الشَّیْءِ وَبِہٖ کے معنے ہیں طَافَ وَاَکْثَرَ الْمَشْیَ حَوْلَہٗ اس نے کسی چیز کے ارد گرد چکر لگایا اور کثرت کے ساتھ گھوما (اقرب) طَافَ یَطُوْفُ بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے.چنانچہ لسان العرب میں لکھاہے طَافَ بِالْقَوْمِ وَ عَلَیْھِمْ کے معنے ہیں اِسْتَدَارَوَجَآءَ مِنْ نَوَاحِیْہِ اس نے چکر لگایا اور کناروں کی
Page 76
طرف سے اس کے پاس آیا انہی معنوں میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جنتیوںکی نسبت فرماتا ہے یَطُوْفُ عَلَیْھِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ (الواقعۃ :۱۸) یعنی اُن کے پاس بار بار نوجوان خادم اُن کی خدمت کے لئے آئیں گے اس جگہ صفا اور مروہ کے گرد گھومنا مراد نہیں بلکہ بار بار اُن کے پاس جانا مراد ہے.تَطَوَّعَ کے معنے ہیں تَبَرَّعَ بِلَا قَصْدِ اُجْرَۃٍ بِاِحْتِمَالِ مُشَقَّۃٍ کسی نیکی کو بغیر اُجرت اور بدلہ کی خواہش کے کرنا(۲) تکلیف اٹھا کر کوئی کام کرنا.اسی لئے والنٹیر کو عربی زبان میں مطاوع کہتے ہیں.کیونکہ وہ بغیر تنخواہ کے آنریری طور پر کام کرتا ہے.(مفردات) شَاکِرٌ جب یہ لفظ خدا تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ انعام نازل کرتا ہے یا حکم بجا لانے پر جزا دیتا ہے.اور جب یہ بندہ کے لئے آئے تو اُس وقت اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر گذار ہوتا ہے.(مفردات) تفسیر.اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ فرماتا ہے.صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں یقیناً اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں.یہ وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حج اور عمرہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے او رسات دفعہ چکر لگایا جاتا ہے.بعض نے کہا ہے کہ چودہ دفعہ دوڑنا چاہیے.مگر یہ کمزور خیال ہے.اصل میں سات دفعہ ہی سعی ہے اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے (بخاری کتاب الحج باب ما جاء فی السعی بین الصفا و المروة).صفا سے شروع کر کے مروہ پر جاتے ہیں اور وہاں سے صفا پرآتے ہیں.یہ سعی چونکہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام کی یاد گار ہے اس لئے یہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نشان ہیں.حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے اسمٰعیل کو عرب کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئو.چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور حضرت ہاجرہ اور اسمٰعیل کو انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس لاکر بسا دیا جہاں پانی کا ایک قطرہ اور گھاس کی ایک پتی تک نہ تھی.صرف ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجوروں کی آپ نے انہیں دی اور پُرنم آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دُعائیں مانگتے ہوئے رخصت ہو گئے.جب پانی ختم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی.اور آخر شدت پیاس کی وجہ سے وہ تڑپنے لگ گئے حضرت ہاجرہ سے اُن کی پیاس کی تکلیف دیکھی نہ گئی.اور وہ پانی کی تلاش میں اِدھر اُدھر دوڑیں.مگر پانی نہ ملا.قریب ہی صفا پہاڑی تھی وہ دوڑ کر اُس پر چڑھ گئیں.کہ شاید کوئی شخص نظر آئے اور وہ اُس سے پانی مانگیں.مگر جب وہاں سے کوئی شخص دکھائی نہ دیا تو دوسری پہاڑی مروہ پر دوڑ کر چڑھ گئیں اور وہاں سے بھی کوئی آدمی نظر نہ آیا.تو پھر صفا کی طرف آئیں اور
Page 77
اس طرح انہوں نے سات چکر کاٹے.آخری چکر میں جب وہ مروہ پر تھیں ان کو ایک آواز آئی.حضرت ہاجرہ نے پکار کر کہا.کہ اے شخص! جس کی یہ آواز ہے اگر تو ہماری مدد کر سکتا ہے تو کر.یہ آواز اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتہ کی تھی.اُس نے کہا ہاجرہ جا اور دیکھ کہ اسمٰعیل کے پائوں کے نیچے خدا تعالیٰ نے ایک چشمہ پھوڑ دیا ہے.چنانچہ وہ واپس آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ جہاں حضرت اسمٰعیل علیہ السلام شدتِ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے.وہاں پانی کا ایک چشمہ پھوٹ رہا ہے اور بڑے زور سے اس میں سے پانی نکل رہا ہے.زمزم کا کنوآں وہی چشمہ ہے جو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے لئے معجزانہ طور پر پھوڑا گیا تھا.چنانچہ اس چشمہ کی وجہ سے پھراس قدر ترقی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں عظیم الشان شہر قائم کر دیا.غرض صفا اور مروہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے اور استقامت کے ساتھ خدمت دین میں حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا.وہ ہاجرہ اور اسمٰعیل کی طرح انہیں اپنے آسمانی نشانات دکھاتا اور دائمی زندگی اور غیر معمولی انعامات عطا کرتا ہے.اگر تم بھی صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی انعامات سے نوازے گا اور تمہیں بھی شعائر اللہ میں داخل کردےگا.فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا.چونکہ بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ صفا اور مروہ پر جانا گناہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَاجُنَاحَ ورنہ یہ مراد نہیں کہ جائو یا نہ جائو تمہارا اختیار ہے.کیونکہ حج اور عمرہ میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی ضروری ہوتی ہے اسی طرح فَـلَاجُنَاحَ کے یہ بھی معنے ہیں کہ طواف جائز ہے.کیونکہ جب اس چیز کے متعلق جسے لوگ حرام جانیں فتویٰ دیا جائے تو اس وقت اس فقرہ کے معنے صرف اس خیال کی نفی کرنی ہوتی ہے نہ کہ اس کا جواز بتانا.حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہی مذہب تھا کہ طواف ضروری ہے چنانچہ بخاری جلد اوّل باب و جوب الصفا و المروۃ وجعل من شعائر اللہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے عروہ بن زبیر سے ایک روایت مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ اس آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ طواف جائز ہے ضروری نہیں.اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بِئْسَمَا قُلْتَ یَا بْنَ اُخْتِیْ اِنَّ ھٰذِہٖ لَوْ کَانَتْ کَمَا اَوَّ لْتَھَا عَلَیْہِ کَانَتْ لَاجُنَاحَ عَلَیْہِ اَنْ لَایَتَطَوَّ فَ بِھِمَا (بخاری کتاب الحج باب وجوب الصفا المروة).یعنی اے میرے بھانجے! تو نے یہ بہت ہی غلط استدلال کیا ہے.اگر یہ بات اسی رنگ میں ہوتی جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو عبارت یوں ہوتی کہ لَاجُنَاحَ عَلَیْہِ اَنْ لَا یَطَّوَّفَ بِھِمَا اور پھر فرمایا وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَیْنَھُمَا فَلَیْسَ لِاَ حَدٍ اَنْ یَّتْرُکَ الطَّوَافَ بَیْنَھُمَا.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی
Page 78
تھی کہ آپ صفا اور مروہ کا طواف کیا کرتے تھے.پس کسی شخص کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اس سنّت کے خلاف معنی کرے بہر حال حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے ان کا یہی مذہب تھا کہ طواف ضروری نہیں.اسی طرح حضرت ابن عباس ؓ حضرت انسؓ عطا اور مجاہد کابھی یہی قول ہے کہ طواف ضروری نہیں.امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ یہ ضروری تو نہیں مگر کسی شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر طواف چھوڑے ہاں اگر بلا ارادہ چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں.مگر مناسب یہی ہے کہ نہ چھوڑے.امام شافعی ؒ اور مالک ؒ کے نزدیک صفا اور مروہ کا طواف واجب ہے اور ارکانِ حج میں سے ہے اور ثوری اور امام ابوحنیفہ ؒکے نزدیک اگر کوئی چھوڑ دے اور بغیر طواف کئے حج پورا کرے تو اُس پر قربانی لازم ہے (جامع البیان زیر آیت ھذا).حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا کہنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ انصار مسلمان ہونے سے پہلے منات بُت کے لئے احرام باندھا کرتے تھے جس کی مشلّل کے پاس لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور اس زمانہ میں جو شخص احرام باندھتا وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو گناہ سمجھتا تھا.جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں دریافت کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم صفا اور مروہ کی سعی گناہ سمجھا کرتے تھے لیکن اب اس کے متعلق کیا حکم ہے.اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (بخاری کتاب الحج باب وجوب الصفا و المروة) پس چونکہ اس وقت ایک جماعت ایسی تھی جو صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے کو جائز نہیں سمجھتی تھی اس لئے اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں.تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ کوئی گناہ نہیں.باقی رہا یہ سوال کہ یہ سعی صرف جائز ہے یا واجب تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم نے صرف یہ بحث اُٹھائی ہے کہ جو لوگ اس کام کو غلطی اور گناہ قرار دیتے ہیں وہ درست نہیں کہتے ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا ضروری ہونا ثابت ہے.پس لَا جُنَاحَ عَلَیْہِ اَنْ یَّطَّوَّفَ بِھِمَا کے یہ معنے نہیں ہیں کہ یہ کام اختیاری ہے کوئی کرے یا نہ کرے بلکہ درحقیقت یہ نصیحت کا ایک طریق ہے کہ جب کسی ضروری بات کی طرف انسان توجہ نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ بات گناہ نہیں.یعنی تم نے جو ادھر توجہ نہیں کی تو شاید گناہ سمجھ کر نہیں کی حالانکہ یہ تو ضروری بات تھی ان معنوں کو سورۃ نساء کی یہ آیت بالکل حل کر دیتی ہے کہ وَاِنِ امْرَاَ ۃٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِھَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَآ اَنْ یُّصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ(النساء: ۱۲۹) یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے نشوز یا اعراض سے ڈرتی ہو تو اگر وہ آپس میں کسی طریق پر صلح کر لیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں اور صلح بہت اچھی چیز ہے.اس آیت میں فَلَاجُنَاحَ عَلَیْھِمَا کے جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے کہ میاںبیوی سوچیں کہ صلح سے رہنا کوئی گناہ نہیں ہے.اگر
Page 79
عورت کے قصور کی وجہ سے مرد کو غصہ ہے.تو وہ چھوڑ دے اور اگر عورت کا قصور نہیں تو مرد اپنی اصلاح کر لے.پس جس طرح اس آیت میں صلح کے متعلق فَلَا جُنَاحَ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اسی طرح فَلَا جُنَاحَ عَلَیْہِ اَنْ یَّطَّوَّفَ بِھِمَا میں جہاں اسے ناجائز سمجھنے والوں کے خیال کی نفی کی گئی ہے وہاں لوگوں کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف کوئی گناہ کی بات نہیں یعنی تم جو ادھر تو جہ نہیں کر رہے تو شاید گناہ سمجھ کر نہیں کر رہے حالانکہ یہ تو ضروری بات ہے.وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیکی کے کاموں میں اس لئے حصہ لیتا ہے کہ ان کے بدلہ میں اُسے کوئی چیز مل جائے تو یہ ایک سودا ہے.اور اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا کوئی پسندیدہ فعل نہیں.عبادت تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کے شکر کے طور پر بجا لانی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اُس پر کئے ہیں.نہ اس لئے کہ اگر میں نے عبادت نہ کی تو مجھے کوئی انعام نہیں ملے گا.عبادت کے مقابلہ میں انعام کی خواہش ایک ادنیٰ خواہش ہے.اصل مقام یہی ہے کہ انسان محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے بے پایاں احسانات کے شکر کے طور پر اپنا سر اُس کے حضور جھکا ئے اور رات دن اُس کی عبادت میں مشغول رہے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا کے الفاظ سے وجوب طواف کی نفی نہیں کی گئی بلکہ مراد یہ ہے کہ عمرہ جتنی بار کرو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا.اسی طرح حج بھی اگر ایک سے زیادہ دفعہ کر سکو تو یہ بھی تمہارے لئے موجب ثواب ہو گا.گویا اس آیت میں وجوبِ طواف کی نفی نہیں بلکہ یہ تحریک کی گئی ہے کہ حج اور عمرہ دونوں باربار کرنے چاہئیں اور بار بار ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے آتے رہنا چاہیے.فَاِنَّ اللّٰہَ شَاکِرٌ عَلِیْمٌ.فرمایاتم خدا تعالیٰ سے سودا نہ کرو بلکہ اُسی پر سچا توکل رکھو.وہ تمہاری نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرےگا اور تمہیں خود ان کی بہتر سے بہتر جزا دےگا.وہ بہت قدردان اور بہت جاننے والا ہے.شاکر کے ساتھ علیم کا اضافہ اس لئے فرمایاکہ انسان کو جو جزائیں ملتی ہیں اُن کی کئی اقسام ہوتی ہیں.بعض جزائیں انسان کو تباہ کر دینے والی ہوتی ہیں اور بعض اس کےلئے مفید اور بابرکت ہوتی ہیں.اگر کسی اندھے کو عینک لگانے کےلئے دی جائے یا کسی جذامی کو اچھے کپڑے دے دئیے جائیں تو وہ چیزیں اُن کے کسی کام نہیں آسکتیں.خواہ وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہوں.اسی لئے فرمایا میں تمہارے حالات کوخوب جانتا ہوں اُنہی کے مطابق میں تمہیں انعام دو ںگااور تمہیں ایسی جزا دو ںگا جو تمہیں دائمی طور پر فائدہ پہنچا نےوالی ہوگی.ترتیب وربط: اِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ والی آیت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وَمِنْ حَیْثُ
Page 80
خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سے جو استدلال میں نے کیا تھا وہی صحیح ہے.کیونکہ تحویلِ قبلہ کے مسئلہ سے صفا اور مروہ کے شعائر ہونےکا کوئی تعلق نہیں اور پھر مسلمان تو وہاں جاہی نہیں سکتے تھے کہ صفا اور مروہ کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا.دراصل اس آیت میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم فتح مکہ کی کوشش کرو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہارے لئے حج کا راستہ کھل جائےگا.اور صفا اور مروہ پر جانا بھی تمہارے لئے ممکن ہو جائےگا.اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الْهُدٰى مِنْۢ جو لوگ اس (کلام) کو جو ہم نے کھلے نشانوں اور ہدایت پر مشتمل نازل کیا ہے.بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ١ۙ اُولٰٓىِٕكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ کےلئے اس کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے چھپاتے ہیں.ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَۙ۰۰۱۶۰ (دوسرے)لعنت کر نے والے (بھی) لعنت کر تے ہیں.حل لغات.بَیّنٰتٌ بَیِّنَۃٌ کی جمع ہے اوربَیِّنٰتٌ اُن براہین اور نشانات کو کہتے ہیںجو اپنی صداقت پر آپ شاہد ہوتے ہیں.البینة کے معنے ہیں الدلیل الحجّة دلیل.(اقرب) ھُدٰ ی وہ تعلیمات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں.اور انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں.لَعْنَۃٌ دُور کرنے کو کہتے ہیں.یعنی کسی کو دھتکاریا جھڑک کر دُور کر دینا.یا اُسے پاس نہ آنے دینا.تفسیر.لَا عِنٌ کے معنے لعنت کرنے والے کے ہوتے ہیں.مگر لعنت کرنے والے دو قسم کے ہو سکتے ہیں.اوّل وہ شخص جسے دوسروں پر لعنتیں ڈالنے اور بُرا بھلا کہنے کی عادت ہو.یہ معنی یہاں چسپاں نہیں ہو سکتے کیونکہ جو شخص اپنے بھائیوں پر لعنتیں ڈالنے والا ہو وہ بداخلاق اور منافق ہوتا ہے اور قرآن کریم کے خلاف عمل کرتا ہے.پس کوئی وجہ نہیں کہ اس قسم کے بد اخلاق اور منافق طبع لوگ خدا تعالیٰ کا ساتھ دیں.کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ظل نہیں ہوتے.لَا عِنٌ سے ایسا شخص بھی مراد ہو سکتا ہے جس کے سپرد اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہو اور وہ لوگ جن کو ایسے فرائض سپرد کئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مامورین ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر یہ اعلان کر
Page 81
دیتے ہیں کہ فلاں شخص پر لعنت پڑے گی اور فلاں اُس کے غضب کا شکار ہو گا.پس لَاعِنُوْن سے مراد وہ ہستیاں ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے لعنت کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے.اَلْکِتٰب سے مراد اس جگہ قرآن کریم ہے اور اَلنَّاس سے مراد یہودی نہیں بلکہ مسلمان ہیں.اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جنگ کے اعلان کے ساتھ جو ابھی ہوا نہیں بلکہ اس کی طرف اشارے ہو رہے ہیں منافقوں کی منافقت ظاہر ہو جائےگی.چنانچہ فرماتا ہے یہ دشمن ایمان لوگ جن کے دلوں میںمنافقت ہے جب ان کو قربانی کے احکام سنائے جاتے ہیں تو وہ ایسی تعلیموں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ ان باتوں کو مخالفوں کےسامنے پیش کیا جائے.اس قسم کے لوگ ہمیشہ علیحدگی میں کہا کرتے ہیں کہ مانا کہ یہ باتیں درست ہیں مگر ان کو دشمنوں کے سامنے پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کی طرف سے خواہ مخواہ مخالفت ہو گی.غرض الہٰی سلسلوں میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکام نازل ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا مخالفوں کی ناراضگی کا موجب ہوتا ہے تو ایسا طبقہ جو دوسروں کی ناراضگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے مداہنت سے کام لےکر ان کو چُھپا نا شروع کردیتا ہے تاکہ نہ لوگوں کو صحیح تعلیم کا علم ہو اور نہ ان کا جذبۂ مخالفت بھڑکے.اس قسم کی مداہنت کمزوری کے دور میں نہیں ہوتی.بلکہ طاقت اور غلبہ کے دَور میں ہوتی ہے.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے منافقین کا کوئی فتنہ نہیں اُٹھا لیکن جب مدنی زندگی آئی اور اسلام نے طاقت پکڑنی شروع کر دی اور یہ اعلان ہونے لگے کہ جب تک مکہ فتح نہ ہو تم نے جنگ کو جاری رکھنا ہے تو جو لوگ کمزور ایمان والے تھے انہوں نے کافروں سے اپنی حفاظت کی طرح ڈالنی شروع کر دی اور کفار کے پاس جا جا کر اس رنگ میں باتیں کرنی شروع کیں کہ محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) تو بڑے اچھے آدمی ہیں وہ تو نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو مگر جو شیلی طبائع والے ان کو اُکساتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے.اسی طرح بعض لوگ کلام الٰہی پر پردہ ڈالتے اور اُسے چُھپاتے اور دشمنوں کو جا جا کر کہتے کہ تم تسلّی رکھو تم پر کوئی تباہی نہیں آسکتی.حالانکہ اگر کفار کے متعلق کوئی خبر دی جائے اور ان کو یہ بتایانہ جائے کہ تمہارے متعلق اللہ تعالیٰ نے فلاں انذاری پیشگوئی کی ہے تو پیشگوئی کی شان اور اس کی عظمت قائم نہیں رہ سکتی.لیکن اگر پہلے سے کہہ دیا جائے کہ تم پر عذاب آئےگا.تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ تم توبہ کر لو تو عذاب کے آنے پر ان پر حجت قائم ہو سکتی ہے.اور عقلمندوں کے لئے ایک بہت بڑانشان بن جاتا ہے لیکن منافق محض اس لئے کہ ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں اور ڈر کے مارے ظاہر نہیں کرتے ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ برکتوں سے کلّی طور پر محروم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے علاوہ
Page 82
جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے لعنت کا اختیار دیا ہوا ہے وہ بھی اُن پر لعنت ڈالیں گے.جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دوسرے مامورین نے بھی اپنے دشمنوں پر لعنتیں ڈالیں بلکہ اب تک لوگ ان پر لعنتیں ڈالتے رہتے ہیں اور قیامت تک ان پر لعنتیں پڑتی رہیں گی.بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں بعض جگہ کئی کئی صفحوں میں مخالفین پر لعنت ڈالی ہے.اور آپ متواتر لعنت لعنت لعنت لکھتے چلے گئے ہیں.اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے نعوذ باللہ انہیں گالیاں دی ہیں.حالانکہ آپ نے گالیاں نہیں دیں بلکہ ایک خدائی فیصلہ کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ لوگ اپنے بُرے اعمال کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی رحمت سے دُور چلے گئے ہیں.جس طرح ایک مجسٹریٹ اگر کسی مجرم کو چھ ماہ قید کی سزا دے تو اس سزا کو درست اور قابلِ قبول قرر دیا جاتا ہے.لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جسے گورنمنٹ نے فیصلہ کا کوئی اختیار نہ دیا ہو کسی مجرم کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ اُسے قید کر دیا جائے تو سب لوگ اُسے پاگل تصور کرتے ہیں.اسی طرح خدا تعالیٰ کے انبیاء بھی رُوحانی عالم کے مجسٹریٹ ہوتے ہیں.اگر وہ مجرموں کو مجرم قرار نہ دیں اور اُن کے بارہ میں اپنا فیصلہ نافذ نہ کریں تو وہ خود مجرم بنتے ہیں.پس اُن کا کسی پر لعنت ڈالنا قانون کے تابع ہوتا ہے اور ایسا کہنا اُن کے فرائضِ منصبی کے لحاظ سے ضروری ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ جو بلاوجہ لعنتیں ڈالتے رہتے ہیں وہ اپنی بداخلاقی اور کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُنہیں دوسروں پر لعنت ڈالنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا.اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اَصْلَحُوْا وَ بَيَّنُوْا فَاُولٰٓىِٕكَ اَتُوْبُ ہاں ! مگر جنہوں نے توبہ کرلی اور اصلاح کرلی اور (خدا کے احکام کو )کھول کر بیان کر دیا تو ایسے لوگوں پر میں فضل عَلَيْهِمْ١ۚ وَ اَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۰۰۱۶۱ کے ساتھ توجہ کروں گا.اور میں (اپنے بندوں کی طرف) بہت توجہ کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں.تفسیر.ہمارے ملک میں عام طور پر لوگ توبہ صرف اس بات کا نام سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایک دو دفعہ یہ فقرہ دہرادیا جائے کہ میری توبہ اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کہہ دیں تو ہمارے سارے گناہ بخشے گئے.حالانکہ صرف منہ سے توبہ توبہ کہہ دینا اور اپنے اعمال میں کوئی تغیر پیدا نہ کرنا کسی انسان کو مغفرت کا مستحق نہیں
Page 83
بنا سکتا.توبہ درحقیقت تین باتوں کے مجموعے کا نام ہے.اول زبان سے اپنے قصور کا اعتراف کرنا.دوم اپنی غلطی کے متعلق دل میں ندامت پیدا ہونا.سوم جو قصور کیا ہے اس کا عملاً ازالہ کرنا.گویا جس مقام پر انسان غلطی کرنے سے پہلے کھڑا ہو اُسی مقام پر وہ رجوع کر کے آجائے اس قسم کی توبہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جو انسانی روح میں واقع ہوتا ہے کیونکہ انسان کے دل میں اپنے گناہوں سے شدید نفرت کا جذبہ پیدا ہونا.اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور روحانیت کے حصول کی خواہش پیدا ہونا اس کے دل کا اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے پگھل جانا.اس کی سفلی خواہشات پر ایک موت کا وارد ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے اُس نے اپنے آپ کو خدا کے لئے صلیب پر لٹکا لیا.اور اپنی پہلی زندگی پر موت وارد کر لی.عیسائی لوگ جو اسلامی توبہ کی حقیقت سے ناواقف ہیں بالعموم اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے توبہ کا دروازہ کھول کر گناہ کا دروازہ کھول دیا ہے.حالانکہ اسلام جس توبہ کو پیش کرتا ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک انسان زبان سے اپنے قصور کا اقرار اور دل سے اپنے فعل پر ندامت کا اظہار نہ کرے اور آئندہ اس سے مجتنب رہنے کا پختہ عہد کرتے ہوئے گذشتہ قصور کا ازالہ بھی نہ کرے.اور کون کہہ سکتا ہے کہ ایسی توبہ گناہ پر دلیری پیدا کر دیتی ہے.گناہ پر دلیری تو اُن کا یہ عقیدہ پیدا کرتا ہے کہ ہمارے تمام گناہ مسیح نے اٹھا لئے ہیں.اب ہمیں کسی فکر کی ضرورت نہیں لیکن وہ توبہ جسے اسلام پیش کرتا ہے اور جو گذشتہ افعال کے کلّی ترک اور آئندہ کے لئے کلّی طور پر نیکی کے راستہ کو اختیار کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف صدق دل سے رجوع کرنے کا نام ہے وہ گناہ پر دلیری پیدا نہیں کر تی بلکہ گناہ کو بیخ وبُن سے اکھیڑ دیتی ہے اور انسان کو ایک نیا روحانی انسان بنا دیتی ہے.اس قسم کی توبہ کرنے والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پوری طر ح خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور دل میں ندامت پیدا کرتے اور اپنے گناہ کو دُور کرتے ہیں اور پھر یہیں تک بس نہیں کرتے بلکہ اَصْلَحُوْا وہ دوسروں سے بھی عیوب دُور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.گویا ان میں اتنا تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں بدیوں سے اتنا بُغض ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی ہی اصلاح نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی بدیوں کو بھی دُور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وَبَیَّنُوْا اور نہ صرف اپنے گرد و پیش کی اصلاح کرتے ہیں بلکہ علی الاعلان دُنیا کے سامنے اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسی میں دنیا کی نجات ہے فَاُولٰٓئِکَ اَتُوْبُ عَلَیْھِمْ فرماتا ہے جب کوئی شخص ایسی توبہ کرتا ہے تو میں بھی فضل کے ساتھ اُس کی طرف رجوع کرتا ہوں.توبہ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنے رجوع برحمت ہونے اور فضل نازل کرنے کے
Page 84
ہوتے ہیں.لیکن جب بندے کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ندامت کا اظہار کرنے اور جرم کا اقرار کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف جھک جانے کے ہوتے ہیں.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے جرم کا اقرار کر کے ندامت کا اظہار کریں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں اور اسلام پر پوری مضبوطی سے قائم ہو جائیں.ایسے لوگوں کے قصور کو معاف کر کے میں پھر ان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہوں جہاں وہ پہلے ہوتے ہیں اور پھر میں اپنے پُرانے طریق پر ان کے لئے فضلوں کا سلسلہ شروع کر دیتا ہوں کیونکہ میں بڑا شفقت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں.اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓىِٕكَ عَلَيْهِمْ جن لوگوں نے انکار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرگئے ایسے لوگوں پر یقیناً اللہ کی اور فرشتوں کی لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَۙ۰۰۱۶۲خٰلِدِيْنَ اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے.وہ اس میں (پڑے )رہیں گے نہ (تو) فِيْهَا١ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ۰۰۱۶۳ ان (پر) سے عذاب ہلکا کیا جائے گااور نہ انہیں (سانس لینے کی )مہلت دی جائے گی.تفسیر.فرماتا ہے ان توبہ کرنے والوں کے بالمقابل جو لوگ کفر کی حالت میں ہی مر گئے.ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو گی.اسی طرح ملائکہ اور سارے انسانوں کی لعنت ہو گی.اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ سارے انسانوں کی اُن پر لعنت ہو گی اس میں اور پہلی آیت میں جس لعنت کا ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ فرق ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے صرف خاص لوگوں کو لعنت کرنے کی اجازت دی تھی.کیونکہ وہاں لعنت سے مراد اُن کی تباہی کی پیشگوئی تھی جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی کیا کرتے ہیں مگر یہاں اُن کے متعلق پیشگوئی کرنا مقصود نہیں کیونکہ یہاں لعنت کرنےوالوں میں سب لوگوں کو شامل کر لیا گیا ہے.اور سارے کے سارے لوگ تباہی کی پیشگوئیاں نہیں کیا کرتے.پس یہاں وہ لعنت مراد ہے جو فطرتی طور پر انسان کے دل سے اٹھتی ہے مثلاً اگر ایک چور کے سامنے بھی اگر چوری کا ذکر ہو تو وہ فوراً کہہ اُٹھتا ہے کہ چور بہت بُرے ہوتے ہیں
Page 85
حالانکہ وہ خود اس فعل کا مرتکب ہوتاہے.اس کی وجہ یہی ہے کہ اُس کی فطرت اسے بُرا قرار دیتی ہے.اسی طرح یہاں لعنت کرنے سے یہ مراد ہے کہ کفار کے افعال پر ہر ایک شخص خواہ نیک ہو خواہ بد فطرتی طور پر لعنت کرتا ہے بلکہ ایک مجرم خواہ اپنی ذات کو بُرا نہ کہے مگر جرم کو ضرور بُرا کہے گا اور اسی کا نام لعنت ہے.خدا اور ملائکہ صفت انسان تو علی الاعلان لعنت کرتے ہیں لیکن باقی دنیا فطری اور اصولی طور پر لعنت کرتی ہے.جیسے کوئی قوم جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتی.کوئی قوم غیبت چوری اور قتل وغیر ہ کو اچھا نہیں سمجھتی.ہاں انفرادی طور پر اگر کوئی ان کا ارتکاب کرے تو خود اس کا اپنا نفس اسے شرمندہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بے ایمانی کا ارتکاب کیاہے.اس جگہ اسی قسم کی لعنت مراد ہے کہ خواہ اپنے فعل کو وہ بُرا نہ کہیں مگر دوسروں کے اُسی قسم کے فعل کو دیکھ کر وہ ضرور بُرا کہتے ہیں چنانچہ کسی سے پوچھ کر دیکھ لو وہ یہی کہے گا کہ جھوٹ بُرا ہے غیبت بُری ہے چوری بُری ہے قتل بُرا ہے ظلم بُرا ہےحالانکہ بعض دفعہ وہ خود ان جرائم کا مرتکب ہوتا ہے اسی طرح کوئی قوم بحیثیت قوم اندھیرے میں چھپ کر کسی کو مار ڈالنے کو اچھا نہیں سمجھتی.کوئی قوم بحیثیت قوم چوری کو اچھا فعل نہیں سمجھتی.کوئی قوم بحیثیت قوم غیبت کو اچھا خیال نہیں کرتی.اسی طرح وہ افراد جو اس قسم کے کاموں کو کرتے وقت انہیں اچھا خیال کرتے ہیں وہ بھی دوسرے موقعہ پر انہیں بُرا اور ناجائز سمجھتے ہیں.غرض یہ لعنت ایسی ہے جو کہیں نہیں مٹتی کیونکہ انسانی فطر ت اس کی ہمنوا ہوتی ہے.پھر فرماتا ہے خٰلِدِیْنَ فِیْھَا یہ قانون ایسا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا.کئی فلسفے اور تہذیبیں بدل گئیں مگر یورپ آج بھی یہی کہتا ہے کہ جھوٹ بُرا ہے ظلم بُرا ہے چوری بُری ہے غیبت بُری ہے.یہ لعنت قائم ہے اورہمیشہ قائم رہے گی.یونانی اور ایرانی فلسفہ بھی یہی کہتا ہے.یوروپین فلسفہ بھی یہی کہتا ہے غرض یہ ایک نہ مٹنے والا اصل ہے اس میں کبھی تغیر نہیں آسکتا.کل اگر کوئی اور تہذیب آئےگی تو وہ بھی یہی کہے گی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتی.لَایُخَفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَلَاھُمْ یُنْظَرُوْنَ فرماتا ہے کہ جب منکرین انبیاء کا پیمانۂ عمل لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنّت ہے کہ وہ آسمانی عذاب میں جکڑے جاتے ہیں اور یہ عذاب ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے ہلکا کیا جاتا ہے اور نہ انہیں ڈھیل دی جاتی ہے.ہاں عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ان کے لئے موقع ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں.لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں اور انکار پر کمر بستہ رہیں اور خدائی نشانات کی تضحیک کرتے رہیں تو ایک دن عذاب الٰہی کے کوڑے ان پر برسنے شروع ہوجاتے ہیں اور پھر ان کی چیخ و پکار بالکل عبث ہوتی ہے.چنانچہ دیکھ لو وہ لوگ جنہوں نے خدا تعالیٰ کے فرستادوں کا مقابلہ کیا.ہزاروں سال گذرنے کے باوجود آج بھی ان پر لعنت پڑ رہی ہے.نمرود کو ہلاک ہوئے ہزاروں سال گذر گئے.فرعون کو
Page 86
سمندر میں ڈوبے ہزاروں سال گذر گئے.وہ فقیہی اور فریسی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا تھا ان پر بھی دو ہزار سال گذر گئے.ابوجہل کو جنگِ بدر میں ہلاک ہوئے بھی چودہ سو سال ہو گئے.مگر آج بھی ہر شریف انسان نمروؔد کا نام لیتا ہے تو اس پر لعنت ڈالتا ہے.فرعون کا نام لیتا ہے تو اس پر لعنت ڈالتا ہے.فقیہیوں اور فریسیوں کا ذکر آتا ہے تو ان پر لعنت ڈالتا ہے ابوجہل کا ذکر آتا ہے تو اس پر لعنت ڈالتا ہے.حضرت عثمانؓ کو شہید کرنے والوں کا ذکر آتا ہے تو ان پر لعنت ڈالتا ہے اور پھر اگلے جہان میں جو انہیں عذاب دیا جا رہا ہے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.غرض یہ عذاب برابر جاری ہے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کا مقابلہ کیا.وَ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ١ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُؒ۰۰۱۶۴ اور تمہارا معبود(اپنی ذات میں )واحد معبود ہے.اس کے سوا کوئی معبود نہیں.بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.تفسیر.فرماتا ہے تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور پھر وہ رحمٰن اور رحیم ہے ایسی کامل صفات رکھنے والے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے تمہیں اپنے دشمنوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری حفاظت کے لئے تمہارا خدا موجود ہے.پس تم اس پر توکل رکھو اور اُسی سے مدد مانگتے رہو.وہ تمہارے دشمن کو تم پر کبھی غالب نہیں آنے دےگا.اور خواہ تمہاری کشتی مشکلات کے بھنور میں کتنے بھی چکر کھائے پھر بھی وہ تمہیں اس میں سے نکال کر ساحل کامیابی پر پہنچا دے گا.مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں بہشتی مقبرہ سے ایک کشتی پر آرہا ہوں اور میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں.راستہ میں کثرت سے پانی ہے اور ایک طوفان سا آیا ہوا معلوم ہوتا ہے جب ہم پُل والی جگہ کے قریب پہنچے.جہاں پہلے صرف دو لکڑیاں لوگوں کے آنے جانے کے لئے رکھی رہتی تھیں تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے اور چکر کھانے لگی ہے اس سے سب لوگ جو کشتی میں بیٹھے تھے ڈرنے لگے جب ان کی حالت مایوسی تک پہنچ گئی تو یکدم پانی میں سے ایک ہاتھ نکلا جس میں ایک تحریر تھی اور اس میں لکھا تھا کہ یہاں ایک پیر صاحب کی قبر ہے ان سے درخواست کرو تو کشتی بھنور میں سے نکل جائےگی.میں نے کہا.یہ تو شرک ہے میں اس کے لئے ہرگز تیار نہیں خواہ ہماری جان چلی جائے میں جوں جوں انکار کرتا گیا چکر بڑھتے گئے.اس پر میرے
Page 87
ساتھیوں میں سے بعض نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اور انہوں نے پیر صاحب کے نام ایک رقعہ لکھ کر بغیر میرے علم کے پانی میں ڈال دیا جب مجھے اس کاعلم ہوا تو میں نے جوش سے کہا کہ یہ شرک ہے اور میں نے فوراً پانی میں چھلانگ لگا دی اور کود کر وہ کاغذ پکڑ لیا اور اُسے باہر لے آیا اور جونہی میں نے ایسا کیا کشتی بھنور میں سے نکل گئی.پس مومن پر خواہ کتنی بھی مشکلات آئیں اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر توکل رکھے اور اُس کے سوا کسی اور کا خوف اپنے دل میں نہ پیدا ہونے دے.یہاں سوال ہو سکتا تھا کہ اچھا اگر وہی ایک معبود ہے تو ہمیں کیا معلوم کہ وہ ہم سے کیا معاملہ کرےگا؟ اس لئے فرمایا کہ وہ رحمٰن و رحیم ہے.وہ ہمیشہ محبت کا ہی معاملہ کرتا ہے اور بندہ کو نہیں چھوڑتا.سوائے اس کے کہ بندہ اُسے خود چھوڑ دے.وہ پہلے بغیر کسی عمل کے انسان پر اپنے بے انتہا فضل نازل کرتا ہے اور جب بندہ ان سامانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو رحیمیت کے ماتحت اس پر مزید احسان کرتا ہے.اور یہ سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے.خدا تعالیٰ کے رحمٰن و رحیم ہونے کی مثال درحقیقت اس بوڑھے کے کھجور لگانے کی سی ہے جس نے بادشاہ سے دو تین دفعہ کئی ہزار روپیہ انعام کے طور پر لے لیا تھا.بادشاہ کا خزانہ تو محدود تھا اس لئے وہ منہ پھیر کر چلا گیا مگر ہمارے خدا کا خزانہ محدود نہیں.ہمارا بادشاہ تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا.اور پھر مانگتے چلے جائو تاکہ میں تمہیں دیتا چلا جائوں.غرض اللہ تعالیٰ بے انتہا فضل کرنےوالا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.اس کے خزانے غیر محدود ہیں وہ کہتا ہے کہ تم پھر کام کرو تو میں پھر تمہیں انعام دوںگا.پھر کرو تو مَیں پھر دوںگا.اور ہمیشہ تمہیں اپنے انعامات سے حصہ دیتا چلا جائوںگا.اس جگہ اِلٰهُكُمْ سے جو شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید کسی اور کا خدابھی ہو گا یا کئی خدا ہوتے ہوں گے اس کا ازالہ لَااِلٰہَ اِلَّا ھُوَسے کر دیا اور الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ سے اس کی کامل صفات بیان کر کے عقلاً بھی کسی اور اِلٰہ کی ضرورت نہ رہنے دی.ترتیب وربط.اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ابراہیمی دعا کے مطابق ہم نے تمہارا منہ بیت اللہ کی طرف کر دیا اور پھر فتح مکہ پر اس نے خاص طور پر زور دیا اور بتایا کہ لوگ فتح مکہ کا انتظار کر رہے ہیں فتح ہونے پر وہ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو جائیںگے اور چونکہ جنگوں میں کئی قسم کی تکالیف پیش آتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی اور دعائیں مانگنے کی طرف توجہ دلائی اور ساتھ ہی حضرت اسمٰعیل ؑ اور حضرت ہاجرہ ؑکی قربانیوں کی مثال بیان کر کے اس حقیقت کو واضح کیا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو
Page 88
کبھی ضائع نہیں کرتا.پھر حج اور عمرہ اور صفا اور مروہ کے طواف کا ذکر کرکے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں حج کا حکم دیا ہے تو ضرور ہے کہ وہ وقت آئے کہ جس میں تم آسانی سے حج کر سکو اور صفا اور مروہ کا طواف کر سکو.غرض ان آیات میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ مکہ ایک دن ضرور فتح ہو گا کیونکہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت کفار مسلمانوں کو بیت اللہ کے قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے.بلکہ اس کے کئی سال بعد بھی کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیا.مگر بتایا کہ ایک وقت آئےگا کہ مکہ پر تمہارا قبضہ ہو گا اور تمہیں حج اور عمرہ میں کسی قسم کی دقّت کا سامنا نہیں کرناپڑےگا.اور پھر آخر میں فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور وہ رحمٰن اور رحیم ہے پس تمہیں اُسی سے تعلق رکھنا چاہیے.اور دشمنوں کی کثرت کو دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے.اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو دنیا میں قائم کرےگا اور تمہیں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے نظارے دکھائےگا.اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کے آگے پیچھے آنے اور وَ الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَاۤ ا ن کشتیوں میں جو انسانوں کو نفع دینے والی چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں.اور اس پانی میں جسے اللہ (تعالیٰ ) اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ نے بادل سے اتارا پھر اس کے ذریعہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا مَوْتِهَا وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ١۪ وَّ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ اور اس میں ہر ایک قسم کے جانور پھیلائے.اور ہواؤں کے ادھر اُدھر پھیلانے میں اور ان بادلوں میں السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ۰۰۱۶۵ جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں (یقینا ً) اس قوم کے لئے جو عقل سے کام لیتی ہے کئی (قسم کے)نشان ہیں.حل لغات.اِخْتِلَافٌ یہ اِخْتَلَفَ کا مصدر ہے اور اِخْتَلَفَ زَیْدٌعَمْرًواکے معنے ہیں کَانَ
Page 89
خَلِیْفَتُہٗ یعنی زید عمرو کا قائم مقام ہوا.وَجَعَلَہٗ خَلْفَہٗ اُسے اپنے پیچھے کیا.اسی طرح اس کے ایک معنے ہیں اَخَذَہٗ مِنْ خَلْفِہٖ.اُسے پیچھے سے پکڑا.(اقرب) مفردات امام راغب میں لکھا ہے اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ کے معنے ہیں فِیْ مَجِیْءِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا خَلْفَ الْاٰخِرِ وَتَعَاقُبِھَا.یعنی رات اور دن کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا.(مفردات) اَلْفُلْکُ کے معنے ہیں اَلسَّفِیْنَۃُ.کشتی (اقرب) یہ لفظ مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی.اسی طرح یہ لفظ واحد اور جمع دونوں طرح بولا جاتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں دونوں کی مثالیں موجود ہیں.ایک جگہ آتا ہے اِذْ اَبَقَ اِلَی الْفُلْکِ الْمَشْحُوْنِ (الصافات: ۱۴۱) یہ واحد کی مثال ہے.دوسری جگہ فرماتا ہے حَتّٰی اِذَا کُنْتُمْ فِی الْفُلْکِ وَجَرَیْنَ بِھِمْ بِرِ یْحٍ طَیِّبَۃٍ(یونس :۲۳) اس میں فُلْک کی طرف ھُمْ جو جمع کی ضمیر ہے پھیری گئی ہے گویا یہاں یہ لفظ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے.تفسیر.پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ١ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ یعنی تمہارا معبود اپنی ذات میں اکیلا اور واحد خدا ہے.اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور وہ بے انتہا کرم کرنےوالا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کے مختلف نظائر کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ہستی کا ثبوت پیش کیا ہے.چنانچہ سب سے پہلے وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی طرف بنی نوع انسان کو توجہ دلاتا ہے.اور فرماتا ہے کہ اس پیدائش میں عقلمند قوم کے لئے بڑے بھاری نشان ہیں.یعنی اگر وہ سوچیں اور غور سے کام لیں تو اس امر کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا انسانی زندگی کے ساتھ تعلق نہ ہو.اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے صرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ہاتھ کام کر رہا ہے.انسان کی کسی کوشش اور عمل کا اس میں دخل نہیں چنانچہ دیکھ لو.ہوا اور پانی اور سورج اور چاند اور ستارے انسان کے کسی عمل کے نتیجہ میں اسے نہیں ملے بلکہ محض اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمانیت کے ظہور کے طور پر ان کو بنی نوع انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے.اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو انسان ایک لمحہ کےلئے بھی دنیا میں زندہ نہ رہ سکتا.پھر آسمانوں اور زمین میں اگر ایک معین قانون کام نہ کر رہا ہوتا اور ایک غیر متبدل نظام جاری نہ ہوتا تب بھی انسانی زندگی بے کار ہو کر رہ جاتی مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدہ کے لئے بنائی وہاں اس نے ہرچیز کو ایک قانون کا بھی پابند بنا دیا تاکہ انسان بغیر کسی خطرہ کے ترقی کر سکے.اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی خدمت میں مصروف رہے.اس حقیقت کو ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اَلَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا١ؕ مَا
Page 90
تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ١ؕ فَارْجِعِ الْبَصَرَ١ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ.ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ( الملک :۴،۵)یعنی بہت برکت والا ہے.وہ خدا جس نے سات آسمان درجہ بدرجہ بنائے اور تو رحمٰن خدا کی پیدائش میں کوئی رخنہ نہیں دیکھتا.تو اپنی آنکھ کو اِدھر اُدھر پھیر کر اچھی طرح دیکھ.کیا تجھے خدا کی مخلوق میں کسی جگہ بھی کوئی نقص نظر آتا ہے ؟پھر بار بار اپنی نظر کو چکر دے آخر وہ تیری طرف ناکام ہو کر لَوٹ آئے گی او ر وہ تھکی ہوئی ہو گی.یعنی اُسے نظامِ عالم میں کوئی بھی خلافِ قانون بات یا نقص نظر نہیں آئےگا.غرض کارخانہ عالم کا ایک معین قانون سے وابستہ ہونا اور زمین وآسمان اور سورج اور چاند اور ستاروں کاا س قانون کے ماتحت ہمیشہ چلتے چلے جانا اور کبھی اس میں کوئی انحراف واقع نہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والایقیناً ایک خدا ہے.اگر ایک سے زیادہ بنانے والے ہوتے جیسا کہ عیسائی تین خدائوں کے قائل ہیں تو ایک ہی قانون ہر جگہ کام کرتا دکھائی نہ دیتا بلکہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی رخنہ واقع ہو جاتا.پس آسمانوں اور زمین کی پیدائش کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت بھی پیش کر دیا اور اپنی وحداینت کا بھی اور یہ بھی ثابت کر دیاکہ وہ رحمٰن ہے یعنی اپنی مخلوق پر بے انتہا کرم کرنے والا اور انہیں ایسے انعامات سے فیضیاب کرنے والا ہے جن میں بندوں کی کسی کوشش یا عمل کا دخل نہیں.اسی طرح آسمانوں اور زمین کی پیدائش اس کی صفت رحیمیت کا بھی ثبوت ہے کیونکہ دنیا میں جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے ماتحت کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہتر سے بہتر نتائج پیدا کرتا ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے زمین میں ہل چلایا ہو اور بیج ڈالا ہو اور پانی دیا ہو اور نگرانی کی ہو اور پھر اسے ایک دانہ کے بدلہ میں کئی کئی سو دانے نہ ملے ہوں.یا کسی نے صحیح محنت کی ہو اور وہ اپنی محنت کے پھل سے محروم رہا ہو.یہ دونوں صفات پہلو بہ پہلو چل رہی ہیں.رحمانیت کا بھی ظہور ہو رہا ہے اور رحیمیت کا بھی ظہور ہو رہا ہے اور ہر چیز اپنے وجود سے خدا تعالیٰ کی طرف انگلی اُٹھا کر اس کی ہستی کا ثبوت پیش کر رہی ہے.درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ہستی کا علم ایسا ہے جو دوسری چیزوں کے علم اور معرفت کے بعد حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ کلّی علم ہے.بعض چیزیں اپنی ذات میں نظر آنے والی ہوتی ہیں ان کے دیکھنے سے انسان کو ان کا علم ہو جاتاہے.مثلاً بچہ کے سامنے اگرہم انگلی رکھیں اور قطع نظر اس سے کہ وہ اس قسم کی تفصیلات معلوم کرے کہ اُس انگلی کے پیچھے ایک پنجہ ہے اور اس پنجہ کے پیچھے ایک بازو ہے اور اس بازو کے پیچھے ایک کندھا ہے.وہ کندھا گردن کے واسطہ سے سر سے ملتا ہے اور اس سر میں ایک دماغ ہے جس کے حکم سے ان چیزوں نے حرکت کی ہے اور پھر یہ انگلی میرے سامنے آئی ہے.وہ یہ سمجھ لے گا کہ اتنی لمبی اور اتنی موٹی ایک چیز میرے سامنے آگئی ہے پس انگلی کا علم باقی علم کی
Page 91
ضرورت کا پابند نہیں.لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم کلی علم کے طور پر ہے اور جب تک جزئیات کا علم نہ ہو اس وقت تک کُلّی علم حاصل نہیں ہو سکتا.ہم خدا تعالیٰ تک اس کی مخلوقات کے ذریعے سے پہنچتے ہیں اور پھر اس میں بھی تکمیل کے بعد تکمیل اور وسعت کے بعد وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے.ایک چیز کے علم کے بعد دوسری چیز کا علم حاصل ہوتا ہے اور دوسری چیز کے بعد تیسری چیز کا.اور تیسری کے بعد چوتھی کا علم حاصل ہوتا ہے.یہاں تک کہ مخلوق کی جزئیات کا علم ہوتے ہوتے انسان خدا تعالیٰ تک معرفت پیدا کرتا جاتا ہے.ایک ادنیٰ سے ادنیٰ انسان بھی اگر غور کرے تو اس کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کی دلیل موجود ہے.جیسے ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تم خدا کو کیوں مانتے ہو تو وہ ہنس پڑا کہ میں اتنا پاگل تو نہیں ہوں کہ خدا کو بھی نہ پہچان سکوں.بکریوں کی مینگنیاں راستہ میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو میں ان کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہوں کہ یہاں سے بکری گذری ہے اونٹ کا پاخانہ پڑا ہوا ہو تو اُسے دیکھ کر میں سمجھ لیتا ہوں کہ ادھر سے اُونٹ گذرا ہے تو کیا اتنی وسیع دنیا کو دیکھ کر میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک خدا موجود ہے جو اس ساری دنیا کا خالق اور اس نظام کا پیدا کرنےوالا ہے.یہ ایک بسیط علم ہے جس پر فلسفیوں نے اعتراض کیا ہے کہ آخر اتفاقات بھی تو ہوتے ہیں.اس لئے خالی زمین و آسمان کی پیدائش اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ان کا کوئی خالق ہے.بعض چیزیں اتفاقاً بھی ہو جاتی ہیں اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاقی بات ہے.قرآن مجید نے فلسفیوں اور مفکرین یورپ کے اس اعتراض کی تردید میں یہ دلیل دی ہے کہ خالی اس دنیا کا وجود بیشک خدا تعالیٰ کے خالق ہونے کی مکمل دلیل نہیں اور تم اس کو اتفاقی کہہ سکتے تھے مگر اس تمام عالم میں ایک ترتیب کا پایاجانا اور ہرچیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑ موجود ہونا اور ہر چیز اور اس کے ذرہ ذرہ میں حکمت کا پایا جانایہ سب کچھ اتفاقی نہیں بلکہ اس دنیا کی ترتیب اور ہر چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑ اور ہر ذرہ کی حکمت یہ سب چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اس سارے نظام اور ساری دنیا کا پیدا کرنےوالا خدا موجود ہے جس نے حکمت کے ماتحت اس ساری دنیا کو پیدا کیا ہے اُس نے انسان کی آنکھ پیدا کی جس میں دیکھنے کی طاقت رکھی تو اس کے مقابل میں سورج کے اندر روشنی پیدا کی جس کے ذریعہ سے انسان دیکھتا ہے.ناک پیدا کی جس سے انسان سونگھتا ہے تو اس کے مقابل میں خوشبو پیدا کی.کان پیدا کیا جس سے انسان سنتا ہے تو اس کے مقابل میں ہوا میں یہ خصوصیت رکھی کہ وہ جنبش کرتی ہے اور اس کے ذریعہ سے کان تک آواز پہنچتی ہے.اب کیا دیکھنے کے لئے آنکھ اگر اتفاقاً پیدا ہو گئی ہے تو اس کے مقابل میں سورج کی روشنی بھی اتفاقاً پیدا ہو گئی؟ سونگھنے کے لئے اگر ناک اتفاقًاپیدا ہو گئی تو کیا اس کے مقابل میں خوشبو بھی اتفاقاً پیدا ہو گئی؟ اگر سننے کے لئے کان اتفاقاً پیدا ہو گئے تو کیا اس کے مقابل میں ہوا کے اندر بھی جنبش کر کے کانوں تک آواز پہنچانے کی قابلیت
Page 92
اتفاقاً پیدا ہو گئی؟ پس ان چیزوں کے اندر اگر کوئی جوڑ نہ ہوتا.کوئی ترتیب نہ ہوتی اور کوئی حکمت نہ ہوتی تو ان کو اتفاق کہا جاسکتا تھا لیکن دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں کوئی ترتیب نہ ہو کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں حکمت نہ ہو.کوئی چیزایسی نہیں جس کا کسی دوسری چیز سے جوڑ اور وابستگی نہ ہو تو ہم کس طرح مان لیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ سارے کا سارا نظام خود بخود اور اتفاقی ہے.مگر یہ دلیل اُسی صورت میں فائدہ دے سکتی ہے جب انسان بڑا ہو اور ان چیزوں پر غور کرے.آنکھوں سے دیکھے؟ دل و دماغ سے سوچے.ادھر ان چیزوں پر نگاہ ڈالے ادھر اپنے دل کے جذبات پر غور کرے.سورج اور چاند کی روشنی کو دیکھے ہوا اور اس کے اثرات پر غور کرے.گرمی اور سردی کے اثرات کو دیکھے.سبزیوں اور ترکاریوں کے پیدا ہونے اور ان کی خاصیتوں پر غور کرے.جب تک وہ ان چیزوں پر غور کرنے اور ان سے نتیجہ نکالنے کی اہلیت نہیں رکھتا اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ تک کس طرح پہنچ سکتا ہے؟ یہ بات خلافِ عقل ہے کہ ایک بچہ ان تمام چیزوں پر غور کر کے اس نتیجہ تک پہنچ جائے کہ ایک خدا موجود ہے.بچہ توسب سے پہلے اپنی ماں سے روشناس ہوتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے پھر جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ ماں کو بھی سب چیزیں باپ ہی لا کر دیتا ہے تو پھر وہ باپ سے محبت کرتا ہے.بڑا ہو کر جب اپنی گلی کے بچوں سے کھیلتا ہے تو پھر ان سے محبت کرتا ہے اگر اس کا کوئی دوست نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ میرے دوست کو بلائو اس کے بغیر میرا گذارہ نہیں.پھر کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں کا شوق پیدا ہوتا ہے تو ان سے محبت کرتا ہے.اگر اُس کی مرضی کے مطابق کھانا نہ ملے یا مرضی کے مطابق کپڑا نہ ملے تو روٹھ جاتا ہے کہ میرا اس کے بغیر گذارہ نہیں پھر اور بڑا ہوتا ہے تو سیر وشکار سے محبت کرتا ہے اور ان چیزوں کے بغیر اپنی زندگی بے لطف سمجھتا ہے.غرض یہ چیزیں ایک ایک کر کے اس کے سامنے آتی ہیں اور ہر ایک کے متعلق وہ یہی اندازہ لگاتا ہے کہ اس کے بغیر میرا گذارہ نہیں.گویا وہی اس کا خدا ہوتا ہے.مگر پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے.پہلے ماں سے محبت ہوتی ہے تو اُسی کو اپنا خدا سمجھتا ہے پھر باپ سے محبت ہوتی ہے تو اسی کو اپنا خدا سمجھتا ہے.پھربھائیوں اور دوستوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کو اپنا خدا سمجھتا ہے پھر کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے تو ان کو اپنا خدا سمجھتا ہے.یہاں تک کہ جب عاقل و بالغ ہوجاتا ہے تو پھر اگر اس پر خدا کا فضل ہو جائے اچھا استاد مل جائے جو اسے علم سکھائے اور ماں باپ بھی اچھی طرح تربیت کرنے والے ہوں تب وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر حقیقی خدا کی طرف آجائےگا اور سمجھ لےگا کہ یہ سب نقلی خدا تھے جن کو میں نے اپنی خواہشات کے ماتحت سب کچھ سمجھ رکھا تھا.اصل خدا تو وہ ہے جو ان سب کا پیدا کرنےوالا ہے.غرض پہلے غیر اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور
Page 93
وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سارا انحصار انہی پر ہے.لیکن ایک ایک کر کے پھر ان کو چھوڑتا چلا جاتا ہے پہلے ماں کی گود کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور اس سے الگ ہونے میں اپنی ہلاکت سمجھتا ہے.پھر بڑا ہوتا ہے تو بھائیوں اور دوستوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور اپنی زندگی کا تمام سُکھ اور راحت انہیں کے ساتھ کھیلنے میں سمجھتا ہے جب ان کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہو تو ماں کے بلانے پر بھی نہیں جاتا.اس کی ساری خوشی کھیلنے میں ہوتی ہے.پھر اور بڑا ہوتا ہے تو سیر و شکار سے محبت ہوتی ہے پھر صحن اور گلی میں کھیلنے کو بھول جاتا ہے اور اس کی ساری خوشیاں سیر وشکار میں مرکوز ہو جاتی ہیں اگر اس کو ان چیزوں سے روکا جائے تو اس میں اپنی ہلاکت سمجھتا ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ ہی آپ ان سب کو چھوڑتا چلا جاتا ہے.یہاں تک کہ جب بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو غور و فکر کے بعد خدا کی حقیقی شکل اس کو نظر آجاتی ہے اور ان تمام چیزوں کو لغو سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے اسی ترتیب طبعی کے ماتحت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ایک ستارہ کو چمکتا ہوا دیکھا تو اس کو اپنا خدا سمجھ لیا.پھر چاند کو دیکھا کہ ستارہ سے بڑا اور اس سے زیادہ روشن ہے تو اس کو اپنا خدا سمجھ لیا.پھر سورج کو دیکھا کہ ستارے اور چاند دونوں سے بہت بڑا اور بہت زیادہ روشن ہے تو اس کو اپنا خدا سمجھ لیا.مگر جب ایک ایک کر کے سب چُھپ گئے تو آپ نے فرمایا اِنِّیْ وَجَّھْتُ وَجْھِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ(الانعام :۹) یعنی میں نے تمام کج راہوں سے بچتے ہوئے اپنی توجہ اس خدا کی طرف پھیر دی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آخر میں آپ خدا تعالیٰ پر ایمان لے آئے.حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ واقعہ تو درست نہیں مگر مفسّرین کا دماغ اس بات تک صحیح پہنچا ہے کہ انسانی دماغ بغیر الہام کے جب ہدایت پاتا ہے تو ادنیٰ سے اعلیٰ تک جاتا ہے.بچے کے نزدیک ابتداء میں اُس کی ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے یا دوسرے لفظوں میں اُس کا خدا ہوتی ہے بلکہ اس کو ماں کی بھی خبر نہیں ہوتی وہ سب سے پہلے پستان ہی کو خدا سمجھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے اس سے دودھ ملتا ہے اگر پستان نہ ملے تو روتا ہے.پھر ماں کو پہچانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے.پھر باپ کو پہچانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے.پھر بھائی سے محبت کرتا ہے پھر ساتھ کھیلنے والوں سے محبت کرتا ہے گلی اور محلے والوں سے محبت کرتا ہے پھر دوسری ضروریات کھانے پینے اور پہننے کی چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر اپنا مقصود سمجھتا ہے.مگر آہستہ آہستہ ان سب کو چھوڑتا چلا جاتا ہے.یہاں تک کہ یہ چیزیں اسے خدا تک پہنچا دیتی ہیں.اگر سال یا چھ مہینے کے بچہ کے اندر بولنے اور سمجھنے کی طاقت ہوتی اور اُسے کہا جاتا کہ تُو بڑا ہو کر اپنی ماں کی گود کو چھوڑ دےگا تو وہ اس بات سے اتنا ہی حیران ہوتا جتنا کہ ایک سائینس دان اس بات سے حیران ہوتاکہ اُسے کہا جائے آگ جلاتی نہیں بلکہ بجھاتی ہے یا سورج روشنی نہیں دیتا.یا چاند کی روشنی
Page 94
مکتسب نہیں بلکہ آپ ہی آپ ہے.غرض جس طرح ایک سائینسدان ان اوپر کی باتوں سے حیران ہوگا وہ بچہ بھی اگر اس کو یہ بات سمجھائی جا سکتی کہ ایک دن وہ اپنی ماں کی گود سے اُتر جائےگا اور اس کی رغبت اپنی ماں سے کم ہو جائےگی حیران ہو تا.اگر سات آٹھ سال کے بچہ کو یہ بات کہہ دی جائے کہ بڑا ہو کر تُو ایک عورت سے شادی کرے گا اور اس سے تیری رغبت زیادہ ہو جائےگی اور تو اپنی ماں کو چھوڑ دےگا تو وہ کہے گا کہ میں ایسا پاگل تو نہیں ہوں کہ اپنی ماں کو چھوڑدوں.وہ اور ہوںگے جو ایسا کرتے ہیں میں تو کبھی اس طرح نہیں کروںگا.پس یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ انسان مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں سے رغبت کرتا ہے اور جس وقت وہ اس چیز سے رغبت کر رہا ہوتاہے اس وقت وہ یہ وہم بھی نہیں کر سکتا کہ ایک دن میں اس چیز کو چھوڑ دوںگا.اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس بات کا اسے خیال بھی نہیں آتا کہ کسی وقت میں اس چیز سے رغبت رکھتا تھا اور اس کے بغیر اپنی زندگی حرام سمجھتا تھا.یہی معنے اَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰـہَ اِلَّااللّٰہُ کے ہیں کہ پہلے انسان غیر اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے جو بظاہر غیر اللہ کا راستہ ہے مگر اللہ تک پہنچنے کا اصل راستہ یہی ہے.اگر بچہ کے اندر پستان کی محبت نہ ہوتی تو اُس کے اندر ماں کی محبت بھی کبھی نہ ہوتی.اگر بچہ کو ماں سے محبت نہ ہوتی تو اس کو باپ سے بھی کبھی محبت نہ ہوتی.اگر بچہ کو باپ سے محبت نہ ہوتی تو اس کو بھائی اور بہنوں سے بھی کبھی محبت نہ ہوتی اگر بچہ کو بھائی بہنوں سے محبت نہ ہوتی تو اس کو دوستوں اور ساتھ کھیلنے والوں سے بھی کبھی محبت نہ ہوتی.اور اگر اس کو اپنے اپنے وقت پر ان اشیاء سے رغبت نہ ہوتی تو سچی بات یہ ہے کہ وہ خدا کو بھی اپنے وقت پر نہ پا سکتا.بات یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت میں جو خلا محسوس کرتا ہے اُس کو پُر کرنے کے لئے وہ مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں سے رغبت کرتا ہے کہ شاید یہ چیز میری ضرورت کو پورا کردے.جب اُس چیز سے اس کی تسلّی نہیں ہوتی تو پھر دوسری چیز سے رغبت کرتا ہے کہ شاید اس چیز سے میری ضرورت پوری ہو جائے.پھرجب اس چیز سے بھی اس کا خلا پُر نہیں ہوتا تو تیسری چیز سے رغبت کرتا ہے کہ شاید یہاں میرا مقصد مل جائے جب اس سے بھی اسے طمانیت حاصل نہیں ہوتی تو پھر چوتھی چیز سے رغبت کرتا ہے کہ شاید یہی میرا مقصود ہو.یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اور آخر خداتک جا پہنچتا ہے اور جب اس کو اللہ مل جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس مقام سے نہیں ہلتا.قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى (النجم : ۴۳) کہ ان تمام چیزوں میں سے جو غیر اللہ ہیں گذر کر ایک دن انسان اپنی منزل مقصود یعنی خدا تک جاپہنچتا ہے اور وہ فوراً ہی اس منزل پر نہیں پہنچ جاتا بلکہ راستہ میں کئی چیزیں آتی ہیں جن کو بچپن کی وجہ سے خدا سمجھ لیتا ہے مگر آہستہ آہستہ اُن سب کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اور ہر چیز اس کی انگلی پکڑ کر اُس کو خدا کے قریب کر دیتی ہے.
Page 95
زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تم نظامِ عالم پر غور کرو تو تمہیں ذرہ ذرہ میں خدا تعالیٰ کا وجود نظر آئےگا.اور تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جس قدر اشیاء پیدا کی ہیں ان تمام کو حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی ان کی پیدائش بلاوجہ نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا مقصد کام کر رہا ہے اور چونکہ وہ مقصد اس دنیا میں پورا ہوتانظر نہیں آتا.اس لئے ضروری ہے کہ انسانی زندگی اسی دنیا تک محدود نہ ہو تاکہ وہ اس نظام کی عظمت کے مطابق اس اعلیٰ مقام کو حاصل کر لے جس کے لئے اس کی پیدائش معرضِ وجود میں آئی ہے.اگر انسان کی زندگی صرف اس دنیا تک ختم ہو جانے والی ہوتی تو اس کے لئے اتنا بڑا نظام جاری کرنا جس کے اسرار کو علوم کی انتہائی ترقی کے باوجود ابھی تک سائینس دان بھی معلوم نہیں کر سکے ایک لغو اور خلافِ عقل فعل قرار پاتا ہے.مجھے یاد ہے ۱۹۴۶ء میں جب ہم نے قادیان میں ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے افتتاح کے لئے ڈاکٹر سرشانتی سروپ صاحب بھٹنا گر ڈائریکٹر سائنٹفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ گورنمنٹ آف انڈیا کو بلوایا تو انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہی کہا کہ آج سائینس دان کے غرور کا سر اس قدر نیچا ہو چکا ہے کہ وہ ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سائینس ان اشیاء کی بھی مناسب تشریح کر سکتی ہے جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہیں اور جب زمین و آسمان میں اس قدر اسرار پائے جاتے ہیں کہ سائینس اپنی تمام ترقی کے باوجود ابھی مادیات میں سے بھی ایک بہت چھوٹے سے حصے کی تشریح کر سکی ہے تو پھر اس وسیع کائنات کو جس وجود کے لئے ایک خادم کے طور پر پیدا کیا گیا ہے اس کی پیدائش کو عبث قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے.پھر فرماتا ہے وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّھَارِ.رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں بھی عقلمند لوگوں کے لئے بڑے بھاری نشان ہیں.اس جملہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمانیت کا ثبوت پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کئے اور سورج اور چاند اور ستارے وغیرہ بنائے.اسی طرح اُس نے اپنی رحمانیت کے ماتحت یہ بھی انتظام کیا ہو اہے کہ رات اور دن کا ایک تسلسل جاری ہے.اور ہر رات کے بعد ایک دن کا ظہور ہوتا ہے.اگر رات نہ آتی تو انسان اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھتا.اور اگر دن نہ چڑھتا تو انسانی زندگی بے کار ہو کر رہ جاتی.پس اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملہ کے ماتحت رات اور دن بنادیئے تاکہ انسان اپنی نیند پوری کر کے قویٰ میں تازگی حاصل کرے اور دن بھر کام کر کے اپنے آپ کو مفید وجود بنائے.رات اور دن کی طرف توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ نے روحانی رنگ میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے مادی ظلمت کو دور کرنے کے لئے انتظام کر
Page 96
رکھا ہے روحانی طور پر بھی ظلمت اور نور کا ایک سلسلہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر رکھے ہیں کہ جس کے نتیجہ میں روحانی ظلمتیں کا فور ہوتی رہتی ہیں.ان سامانوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ ملائکہ انسانی قلوب میں نیک تحریکات کرتے رہتے ہیں اور انہیں ظلمات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں.لیکن جب بنی نوع انسان کی اکثریت ظلمت میں گرفتار ہو جائے اور ملکی تحریکات ان پر اثر نہ کریں اور شیطان اُن پر تسلّط جمالے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور مامورین کے ذریعہ ان کی ظلمتوں کو دُور کرنے کی کوشش کرتا ہے.یہ لوگ روحانی عالم کے آفتاب و ماہتاب ہوتے ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ستاروں کی طرح دنیا کی ہدایت کا موجب بنتے ہیں.غرض اِخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّھَارِ میں اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کے اس فیضان کی طرف توجہ دلائی ہے جس کے ذریعہ ملائکہ اور انبیاء اور مامورین اور مجدّدین اور اولیاء وغیرہ بنی نوع انسان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتے ہیں اور دنیا کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں.وَالْفُلْکِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے کشتیوں اور جہازوں کے بغیر تم سمندروں میں نہ ایک طرف کا مال دوسری طرف پہنچا سکتے ہو اور نہ وہاں سے کوئی مال اپنے استعمال کے لئے لا سکتے ہو.اسی طرح خدا تعالیٰ نے رُوحانی دنیا میں بھی بعض ایسے وجود بنائے ہیں جو لوگوں کے لئے کشتی کاکام دیتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے فیضان لاتے ہیں اور تمہیں زمین سے اُٹھا کر خدا تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں پھر جس طرح وہی شخص سمندری طوفانوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو کشتی میں سوار ہو اسی طرح روحانی بلائوں اور آفات سے بھی وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اپنے زمانہ کے روحانی نجات دہندہ کی کشتی میں سوار ہو.وَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِمِنْ مَّآءٍ میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو حیاتِ تازہ بخشنے کے لئے آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے اسی طرح وہ لوگوں کی روحانی تشنگی فرو کرنے کے لئے آسمان سے ہی وحی نازل کیا کرتا ہے.مگر افسوس ہے کہ لوگ جسمانی بارش کو تو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں لیکن جب آسمان سے وحی الہٰی کی بارش نازل ہو تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓ سے وحی الہٰی کی بارش سے فائدہ اُٹھانے اور نہ اُٹھانے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں تین قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مثال اچھی زمین کی طرح ہوتی ہے.جو نرم ہو.پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی قابلیت رکھتی ہو اور پھر اچھی کھیتی اُگاسکتی ہو.جب بارش نازل ہوتی ہے تو وہ زمین بارش کے پانی کو سمیٹ لیتی اور اُسے اپنے اندر جذب کرلیتی ہے اور پھر زمین سے کھیتی نکلتی اور لوگوں کے کام آتی ہے گویا وہ خود بھی پانی پیتی
Page 97
ہے اور باقی لوگوں کے لئے بھی غذا مہیاکرتی ہے.اور دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مثال اس زمین کی طرح ہوتی ہے جو سخت ہو لیکن اپنے اندر نشیب رکھتی ہو.جب پانی گِرتا ہے تو وہ اس زمین میں جمع ہو جاتا ہے اور گو ایسی زمین خود پانی نہیں پیتی لیکن چونکہ وہ پانی کو جمع کر لیتی ہے اس لئے وہ پانی جانور پیتے ہیں آدمی استعمال کرتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو اس پانی سے سیراب کرتے ہیں لیکن ایک تیسری قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی مثال اس سخت اور پتھریلی زمین کی طرح ہوتی ہے جو نہ صرف سخت اور پتھریلی ہو بلکہ مسطّح اور ہموار بھی ہو.اس میں کوئی گڑھا نہ ہو جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو نہ وہ آپ پانی پیتی ہے کیونکہ وہ سخت اور پتھریلی ہوتی ہے اور نہ پانی جمع کرتی ہے کیونکہ وہ مسطّح اور ہموار ہوتی ہے (بخاری کتاب العلم باب فضل من عَلِمَ و عَلَّمَ).پھر فرمایا پہلی مثال تو اس شخص کی ہے جو عالم باعمل ہو.وہ دین حاصل کرتا ہے اور نہ صرف خود اس کے احکام پر عمل کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور ان کو عامل بنانے کی کوشش کرتا ہے گویا وہ عالم بھی ہوتا ہے اور عامل بھی ہوتا ہے.وہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور معلّم بھی ہوتا ہے.لیکن تیسری قسم کا آدمی نہ عامل ہوتا ہے اور نہ معلم ہوتا ہے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے.دوسری مثال بوجہ اس کے کہ دونوں مثالوں سے حل ہو جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی مگر ہر شخص ادنیٰ غور سے سمجھ سکتا ہے کہ دوسری مثال اس شخص کی ہے جو معلم تو ہے مگر عامل نہیں.وہ دین سیکھتا ہے اُس کے احکام سنتا ہے اس کی تعلیموں سے واقفیت رکھتا ہے مگر خود دین دار نہیں ہوتا.ایسا شخص چونکہ خدا اور اس کے رسول کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے اس لئے وہ بھی ایک مفید وجود ہوتا ہے گو ذاتی طور پر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا.بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا ہے.اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے آنے پر یہی تین گروہ دنیا میں نظر آتے ہیں یعنی کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی تعلیموں پر عمل کرتے اور وحی الٰہی کی بارش سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اعراض سے کام لیتے اور انبیاء کا انکار کر دیتے ہیں.اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دین کو سمجھتے تو ہیں مگر اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے.اللہ تعالیٰ نے اس جگہ مادی بارش کا ذکر فرماکر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح تم بارش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہو.اسی طرح تمہارا فرض ہے کہ تم اس روحانی بارش سے بھی فائدہ اُٹھائو جو محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل ہوئی ہے اور ان پتھروں کی طرح مت بنو جو بارش کا کوئی قطرہ اپنے اندر جذب نہیں کرتے.پھر جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے توزمین کی اندرونی تہوں میں جو پانی مخفی ہوتا ہے اس میں بھی جو ش پیدا ہوتا ہے اور کنوئوں کا پانی بھی چڑھ آتا ہے اسی طرح انبیاء پر جب وحی الہٰی کی بارش نازل ہوتی ہے تو
Page 98
عوام النّاس کو بھی کثرت کے ساتھ خوابیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی توجہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف پھر جاتی ہے چنانچہ اس زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوا.اور حضرت مسیح موعو د علیہ السلام کی صداقت میں ہزار ہا لوگوں کو خوابیں آئیں.میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی خوابیں اکٹھی کی جائیں تو ایک بہت بڑی کتاب بن سکتی ہے.اسی طرح وحی الٰہی کے فیضان کے دائرہ کو اللہ تعالیٰ اس رنگ میں بھی وسیع کر دیتا ہے کہ جو لوگ انبیاء پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں میں بھی ایک نئی روشنی پیدا کر دیتا ہے اور ان کی عقلیں تیز ہو جاتی ہیں ان کا فکر بلند ہو جاتا ہے ان کی فراست ترقی کرجاتی ہے اور ان کی دماغی صلاحیتیں زیادہ تیز ی سے اُبھرنے لگتی ہیں.پھر فرماتا ہے خدا تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ وَ بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ.اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے ہیں اس میں مادی جانوروں کے علاوہ ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو انبیاء کے آنے سے پہلے مُردہ کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور ان میں روحانی زندگی کی کوئی رمق تک نظر نہیں آتی لیکن جب آسمانی صُور پُھونکا جاتا ہے تو اس وقت ایسے ُمردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور لولے لنگڑے بھی چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں.پھر یہ لوگ جو مختلف ملکوں اور مختلف قوموں اور مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف علوم و فنون اور مختلف قابلیتوں کے مالک ہوتے ہیں نبی کی آواز پر لبیک کہنے کے بعد دین کی اشاعت کے لئے دنیا میں چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور اپنی تبلیغی جدوجہد سے لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کو دین کی طرف کھینچ لاتے ہیں جو اس کے دین کی رونق اور تازگی کا موجب بنتے ہیں.ان معنوں کے لحاظ سے دَآبَّةٍ ٍ سے اُن مومنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو زمین کی روحانی رونق اور آبادی کا باعث ہوتے ہیں اور جن سے موجودہ اور آئندہ نسلیں ہزاروں قسم کے مادی اور روحانی فوائد اُٹھاتی ہیں.وَ تَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ رحیمیت کا ثبوت پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ صفتِ رحمانیت کے ماتحت اللہ تعالیٰ کے جس قدر فیضان ہیں ان میں تو کافر بھی برابر کے شریک ہیں لیکن رحیمیت کے دائرہ میں جب مومن اور کافر کامقابلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تائید مومنوں کو کامیاب کرتی اور کفار کو ان کے بدارادوں میں ناکام کر دیتی ہے اس جگہ استعارہ کے طور پر ہوائوں سے وہ ہوائیں مراد ہیں جو خاص خاص وقتوں میں چلا کرتی ہیں خصوصاً وہ ہوائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے چلیں اور جنہوں نے آپ کے انوار کو ساری دنیا میں پھیلا دیا مثلاً جنگِ بدر کے موقعہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اور کنکریوں کی ایک مٹھی پھینکی تو اُسی وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی تیز ہوا چلی جس نے مومنوں کی تائید کی.اور کفار کو ایسا بے دست و پا
Page 99
کر دیاکہ تھوڑی دیر میں ہی جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور کفار کے بڑے بڑے لیڈر خاک و خون میں تڑپنے لگے اور ان کے مسلّح اور آزمودہ کار سپاہی میدان سے منہ پھیر کر بھاگ نکلے.(السیرة النبویة لابن ہشام ذکر رؤیا عاتکۃ بنت عبد المطلب رمی الرسول للمشرکین بالحصباء).پھر غزوۂ احزاب میں بھی ایسا ہی ہوا اور خدا تعالیٰ نے آپ کی تائید میں ہوا چلائی اور کفار بد حواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے.چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک رات سخت آندھی چلی جس نے قناطوں کے پردے توڑ دیئے.چولھوں پر سے ہنڈیاں گرادیں اور بعض قبائل کی آگیں بُجھ گئیں.مشرکین عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ ساری رات آگ جلائے رکھتے تھے اور اس کو نیک شگون سمجھتے تھے اور جس کی آگ بُجھ جاتی تھی وہ خیال کرتا تھا کہ آج کا دن میرے لئے منحوس ہے اور وہ اپنا خیمہ اٹھا کر لڑائی کے میدان سے پیچھے ہٹ جاتا تھا جن قبائل کی آگ بجھی انہوں نے اس رواج کے مطابق اپنے خیمے اٹھائے اور پیچھے کو چل پڑے.ان کو دیکھ کر ارد گرد کے قبائل نے سمجھا کہ شاید یہود نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر شبخون مار دیا ہے اور ہمارے آس پاس کے قبائل بھاگ رہے ہیں.چنانچہ انہوں نے بھی جلدی جلدی اپنے ڈیرے سمیٹے اور میدان سے بھاگنا شروع کر دیا.ابوسفیان اپنے خیمہ میں آرام سے لیٹا تھا کہ اس واقعہ کی خبر اُسے بھی جا پہنچی وہ گھبرا کر اپنے بندھے ہوئے اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اس کو ایڑیاں مارنی شروع کر دیں.آخر کسی نے اُسے توجہ دلائی کہ وہ یہ کیا حماقت کر رہا ہے اس پر اس کے اونٹ کی رسیاں کھولی گئیں اور وہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت میدان سے بھاگ گیا (السیرة النبویۃ لابن ہشام، غزوةخندق).پھر ہوائوں کی طرح بارشیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی تائید میں برسیں اور بادلوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا چنانچہ جنگِ بدر کے موقعہ پر جبکہ صحابہؓکو پانی کی سخت ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا اور ان کی زمین بھی جو ریتلی تھی اور میدان جنگ بننے والی تھی سخت ہو گئی.اُدھر کافروں کی زمین جو سخت تھی بارش کی وجہ سے ایسی خراب ہو گئی کہ وہ اُس پر پھسلنے لگ گئے(السیرة النبویۃ لابن ہشام ذکر رؤیا عاتکۃ بنت عبد المطلب).اسی طرح مدینہ میں آپ کی دُعا کی برکت سے ایک دفعہ کئی دن بارش ہوتی رہی لیکن جب وہ بارش تکلیف کی صورت اختیار کرنے لگی اور مومنوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو آپ ہی کی دُعا کی برکت سے وہ رُکی اور مدینہ سے ہٹ کر اردگرد کے علاقوں پر برسنے لگ گئی.(بخاری کتاب الدعوات ، باب الدعاء غیر مستقبل القبلۃ).اسی طرح جب مکہ والوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی شدید مخالفت کی اور بار بار عذاب کا مطالبہ کیا
Page 100
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ویسا ہی سات سالہ قحط نازل فرمائے جیسا کہ اس نے یوسفؑ کے زمانہ میں نازل کیا تھا.چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی اس بد دُعا کی وجہ سے حجاز میں ایسا شدید قحط پڑا کہ لوگوں کو مردار اور ہڈیاں اور چمڑے تک کھانے پڑے اور ان کی صحتیں اس قدر کمزور ہو گئیں کہ انہیں ہروقت آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آتا تھا اور یہ عذاب پورے سات سال تک ممتد رہا.آخر لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ مضر یعنی قبائلِ حجاز کے لئے دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو دُور کرے.چنانچہ آپؐ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں نازل فرمائیں اور قحط دُور ہوا بلکہ ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ خود ابوسفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) تیری قوم ہلاک ہو گئی.دعا کر کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دُور کرے.چنانچہ آپ نے دُعا فرمائی اور یہ عذاب دُور ہوا(بخاری کتاب تفسیر القرآن سورۃ دُخان باب ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون).یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوائیں بھی مسخر کر دی تھیں اور بادل بھی مسخر کر دیئے تھے اور کامل مومنوں کے لئے بھی وہ ایسا ہی کیا کرتا ہے.بے شک ہوائیں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں اور بارشیں ہمیشہ برستی رہتی ہیں مگر بدر اور احزاب کی ہوائوں نے بتا دیا کہ وہ مومنوں کے لئے بشارت اور کافروں کے لئے عذاب تھیں.اسی طرح بارشیں بھی بے شک عام طور پر ہوتی رہتی ہیں مگر بدر اور مدینہ کی بارشوں نے بتا دیا کہ وہ مسخر شدہ تھیں اور مسخر شدہ بارشیں اور ہوائیں ہمیشہ مومنوں کی تائید اور کفار کی تذلیل کے لئے جاری ہوتی ہیں اور ایسے امور تقدیر خاص کے ماتحت جاری ہوتے ہیں.وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ(میں)سے(اللہ کے) ہمسر بنا تے ہیں.وہ ان سے اللہ کی محبت کی طرح يُّحِبُّوْنَهُمْ۠ كَحُبِّ اللّٰهِ١ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِؕ محبت کرتے ہیں.اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ(ہی) سے محبت کرتے ہیں.وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ١ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ اور جو لوگ (اس )ظلم کے مرتکب ہوئے (ہیں) اگر وہ (اس گھڑی کو ) جب وہ عذاب کو (سامنے) دیکھیں گے
Page 101
لِلّٰهِ جَمِيْعًا١ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ۰۰۱۶۶ (کسی طرح اب) دیکھ لیتے (تو جان لیتے )کہ سب قوت اللہ ہی کو ہےاور یہ کہ اللہ سخت عذاب (دینے ) والا ہے.حلّ لُغات.اَنْدَادًا.یہ نِدٌّ کی جمع ہے اور اَلنِّدُّ کے معنے ہیں اَلْمِثْلُ وَلَایَکُوْنُ اِلَّا مُخَالِفًا.نِدّ مثل کو کہتے ہیں.اور یہ لفظ ہمیشہ مدّ مقابل کے لئے بولا جاتا ہے.یُقَالُ مَالَہٗ نِدٌّ اَیْ مَالَہٗ نَظِیْرٌ کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نِد نہیں یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں.اس کی جمع انداد آتی ہے.(اقرب) یہاں اِذْ.حِیْنَ کے معنے میں استعمال ہوا ہے اور حِیْن کے معنے وقت کے ہیں.اسی طرح اس جگہ لَوْ کی جزاء محذوف ہے جو کہ یَعْلَمُوْا ہے.معنے اس طرح ہوںگے کہ اگر یہ ظالم لوگ اس گھڑی کو جس میں اُن پر عذاب نازل ہو گا دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہو جائے کہ سب قوت اللہ ہی کے لئے ہے.تفسیر قرآن کریم میں مشرکوں کے معبودوں کے لئے چار الفاظ استعمال کئے گئے ہیں.(۱) نِدّ (۲) شریک (۳) اِلٰہ (۴)ربّ.اور یہ چاروں نام چار قسم کے شرکوں پر دلالت کرتے ہیں.نِدّ شریک فی الجوہر کو کہتے ہیں یعنی ایسی ہستی کو جس کی محض عبادت ہی مدِّنظر نہ ہو بلکہ جیسے خدا تعالیٰ کی ذات ہے ویسے ہی اس چیز کو ازروئے ذات سمجھا جائے اور شریک وہ ہے جسے کاموں میں شریک باری تعالیٰ قرار دیا جائے خواہ بعض صفات میں یا کل صفات میں.خواہ اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے اور اِلٰہ یعنی معبود کا لفظ جب خدا تعالیٰ مشرکوں کی نسبت استعمال کرے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو.یہ لفظ بھی نِدسے وسیع ہے کیونکہ عام طور پر وہ بھی اِلٰہ قرار دیئے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے شریک فی الجوہر تسلیم نہیں کیے جاتے.جیسے ہندوئوں وغیرہ کے دیوتا ہیں.اور ربّ ان ہستیوں کو کہا جاتا ہے جن کی ہر ایک بات بلا تمیز خیر و شر مان لی جائے بغیر اس کے کہ لوگ ان کی عبادت کریں یا انہیں خدا تعالیٰ کی صفات میں شریک قرار دیں.ان چاروں قسم کے شرکوں کی مثالیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں.نِدّ قرار دینے والی وہ مسیحی اقوام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دیتی ہیں وہ انہیں صفاتِ الوہیت کی وجہ سے خدا قرار نہیں دیتیں بلکہ اس وجہ سے خدا قرار دیتی ہیں کہ ان کے نزدیک وہ ازلی ابدی ہیں.یعنی وہ انہیں شریک فی الجوہر ہونے کے لحاظ سے خدا مانتی ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ خدائی کی وہ تمام صفات جو ذات کے لحاظ سے خدا تعالیٰ میں موجود ہونی ضروری ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں.یا جیسے پارسی لوگ دو الگ الگ خدائوں کے قائل ہیں.یزدان کو وہ روشنی کا خدا سمجھتے ہیں اور اہرمن کو تاریکی کا خدا قرار دیتے ہیں(انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجین اینڈ
Page 102
ایتھکس زیر لفظ Zoroastrianism).اس کے مقابلہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض ہستیوں کو صرف شریک قرار دیتے ہیں یعنی بعض کاموں پر انہیں متصرف تو تسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی پرستش نہیں کرتے.گویا انہیں صرف شریک فی الصفات مانتے ہیں جیسا کہ عرب کے لوگ تھے وہ جنّات وغیرہ کو حکم اور تصرف میں تو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے مگر انہیں معبود یا رب یا نِدّ خیال نہیں کرتے تھے صرف اُن کا یہ اعتقاد تھا کہ فلاں وادی میں جسے وہ سید الوادی قرار دیتے تھے جِنّ متصرف ہے اور وہ اس میں آتا جاتا ہے.وہ اس کا ادب بھی کرتے تھے اور خدا تعالیٰ کی طرح اس سے ڈرتے بھی تھے لیکن اس کی عبادت نہیں کرتے تھے.(تفسیرقرطبی سورۃ الجن زیر آیت ۴ تا ۷) اِلٰہ یعنی معبود کا لفظ نِدّ سے وسیع ہے.چنانچہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بعض ہستیوں کو معبود تو سمجھتے ہیں اور اُن کی عبادت بھی کرتے ہیں مگر انہیں خدا تعالیٰ کا شریک فی الجوہر تسلیم نہیں کرتے.جیسے ہندو اپنے دیوتائوں کی عبادت کرتے ہیں مگر اُن کو متصرف یا شریک فی الجوہر قرار نہیں دیتے.اسی طرح ان میں ماں باپ کی عبادت بھی پائی جاتی ہے مگر ان کو شریک یا رب یا نِدّ نہیں سمجھا جاتا.چوتھا نام ربّ ہے اور گو اس کے اصل معنے پیدا کرکے کمال تک پہنچانے والے کے ہیں.مگر اصطلاح مذاہب میں ہر ایک مربی اور سردار کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے ایسے لوگ مراد ہوتے ہیں جن کی ہر ایک بات بلاتمیز خیر و شر مان لی جائے.جیسے گم گشتہ اقوام میں پیروں فقیروں کے متعلق اعتقادرکھا جاتا ہے.اسلام اجتہادی مسائل میں دوسروں کی اطاعت جائز قرار دیتا ہے لیکن جس شخص کی خدا اور انبیاء کے حکم کے خلاف نصوص صریحہ میں اطاعت کی جائے وہ گویا ربّ سمجھا جاتا ہے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اِتَّخَذُوْۤا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ (التوبۃ :۳۱) یعنی یہود نے اپنے احبار اور راہبوں کو خدا کے سوا اپنا ربّ بنا لیا ہے.ان چاروں الفاظ میں سے اِلٰہ اور ربّ کے الفاظ تو خدا تعالیٰ کے لئے بھی استعمال کر لئے جاتے ہیں لیکن نِدّ اور شریک کے الفاظ صرف معبود انِ باطلہ کے لئے ہی استعمال ہوتے ہیں.اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ جہاں نِدّ کا لفظ استعمال ہوگا وہاں شریک فی الجوہر مراد ہو گا.(اگر جوہر میں مشابہت نہ ہو تو وہ چیز مثل کہلائےگی نِدّ نہیں) اور جس جگہ شریک کا لفظ استعمال ہو گا وہاں شریک فی الصفات مراد ہو گا خواہ اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے اور جہاں اِلٰہ یعنی معبود کا لفظ ہو گا وہاں صرف عبادت کو مدِّنظر رکھا جائےگا.خواہ انہیں خدا کا شریک فی الجوہر تسلیم نہ کیا جائے.اور جہاں ربّ کا لفظ استعمال ہو گا وہاں ایسی ہستیاں مراد ہوںگی جن کی ہر ایک بات خیر و شر کی تمیز کے بغیر مان لی جائے اور خدا اور اس کے رسول کے احکام کی پرواہ نہ کی جائے.قرآن کریم میں ان سب اقسام کے شرک کا
Page 103
ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ١ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.(آل عمران: ۶۵) یعنی تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب! کم سے کم ایک ایسی بات کی طرف تو آجائو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے.اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں.کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم آپس میں ایک دوسرے کو ربّ نہ بنایا کریں.لیکن اگر اس دعوتِ اتحاد کے بعد بھی وہ لوگ پھر جائیں تو ان سے کہہدو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں.اس آیت میں (۱) لَانَعْبُدَ اِلَّا اللّٰہَ (۲) وَلَا نُشْرِکَ بِہٖ شَیْئًا (۳) وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فرما کر اِلٰہ یعنی معبود اور شریک اور ربّ تینوں اقسامِ شرک کی نفی تو صراحتًا کی گئی ہے.مگر نِدّ کی ضمنی طور پر نفی کی گئی ہے.کیونکہ نِدّ ان تینوں کے اندر شامل ہے.یعنی جو نِدٌّ ہو گا.وہ بغیر عبادت اور شرک فی الصّفات اور اطاعتِ کامل کے نہیں ہو گا.اور جب غیر اللہ کی عبادت اور شرک فی الصفات اور رب بنانے کو گناہ قرار دے دیا گیا تو نِدّکی خود بخود نفی ہو گئی لیکن اس کے علاوہ لَا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰہَ سے بھی نِدّ کی نفی ہو جاتی ہے.غرض اسلام توحید کے جس بلند ترین مقام پر بنی نوع انسان کو پہنچانا چاہتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نہ تو کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک فی الجوہر سمجھے.نہ کسی کو اس کے کام میں شریک قرار دے خواہ اس کی عبادت کی جائے یا نہ کی جائے.نہ غیر اللہ میں سے کسی کی پرستش کی جائے اور نہ خدا اور اس کے انبیاء کے احکام کے خلاف کسی کی اس طرح اطاعت کی جائے جس طرح خدا تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے.یہ تمام چیزیں توحید حقیقی کے منافی ہیں.يُـحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ کے دو معنے ہیں.ایک تو یہ کہ وہ ان انداد سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے.دوسرے جتنی محبت انہیں خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے اتنی ہی وہ اپنے انداد سے بھی کرتے ہیں.اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ خدا تعالیٰ سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے دلوں میں خدا تعالیٰ سے کوئی حقیقی محبت نہیں پائی جاتی.پہلے معنے کے لحاظ سے تو دونوں سے ان کی محبت یکساں معلوم ہوتی ہے لیکن دوسرے معنے کو مدِّنظر رکھتے ہوئے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا خدا تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ محض ایک لاف زنی ہے ورنہ ان دونوں محبتوں میں بڑا بھاری فرق ہوتا.وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ کے بھی دو معنے ہیں ایک تو یہ کہ مومن مشرکوں کی نسبت خدا تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں.یعنی جو محبت مشرکوں کو خدا تعالیٰ سے ہے اس سے بہت زیادہ محبت مومن اپنے خدا سے کرتے ہیں.یا
Page 104
مشرک اپنے بتوں سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ محبت مومن خدا تعالیٰ سے کرتے ہیں.اور دوسرے معنے یہ ہیں کہ مومن خدا تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں سے جو محبت کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی محبت کی نسبت وہ خدا تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اگر دونوں محبتوں کا مقابلہ ہو جائے تو خدا تعالیٰ کی محبت کا پہلو ہمیشہ بھاری ہوتا ہے.قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر اس محبت کی ان الفاظ میں تشریح فرمائی ہے کہقُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ا۟قْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ١ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ(التوبۃ: ۲۴) یعنی کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا تمہارے خاوند اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے بگڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو.خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کے راستہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں تو تم کو خدا سے کوئی محبت نہیں.تب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو اور خدا تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو کبھی اپنا راستہ نہیںدکھاتا.یعنی کامل محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اس کی خاطر ہر ایک چیز کو قربان کر دے.اگر اس بات کے لئے وہ تیار نہیں تو منہ کی باتیں اس کے لئے کچھ بھی مفید نہیں.یوں تو ہر شخص کہہ دیتا ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے بلکہ مسلمان کہلانے والا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس اقرار کا اثر اس کے اعمال پر اس کے جوارح پر اور اس کے اقوال پر کیا پڑتا ہے.وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کوسرشار بتاتے ہیں اور آپ کی تعریف میں نعتیں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں بلکہ بعض تو خود بھی نعتیں کہتے ہیں.آپ کے احکام کی فرمانبرداری کی طرف ان کو کچھ بھی توجہ نہیں ہوتی وہ خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس سے ملنے کے لئے کوئی کوشش نہیں کرتے.ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی عزیز آجائے تو وہ سو کام چھوڑ کر اس سے ملنے کے لئے جاتا ہے.اپنے دوستوں اور پیاروں کی ملاقات کا موقعہ ملے تو پھُولا نہیں سماتا.حکام کے حضور شرف بار یابی حاصل ہو تو اس کی گردن فخر سے اونچی ہو جاتی ہے لیکن لوگ خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز کے قریب بھی نہیں جاتے.یا نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی.یا اگر باقاعدہ بھی پڑھی تو ایسی جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ معلوم نہیں ہوتا کہ سجدہ سے انہوں نے کب سر اٹھایا اور کب دوبارہ سجدہ کیا.جس طرح مرغا چونچیں مار کر دانہ اٹھاتا ہے اسی طرح وہ بھی سجدہ کر لیتے ہیں نہ خشوع ہوتا ہے نہ خضوع.اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزہ کا بدلہ اپنے آپ
Page 105
کو قرار دیا ہے.مگر لوگ خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کا دامن پکڑنے کے لئے نہیں جاتے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے.خدا تعالیٰ کی محبت ظاہر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق دباتے ہیں.جھوٹ بولتے ہیں.بہتان باندھتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عشق کا اظہار کرتے ہیں لیکن قرآن کریم کا مطالعہ اور اس پر غور کرنے کی توفیق ان کو نہیں ملتی.غرض محبت کا دعویٰ اور شے ہے اور حقیقی محبت اور شے ہے.قرآن کریم بتاتا ہے کہ انسان اس وقت تک کبھی سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ عملاً خدا تعالیٰ سے ایسی محبت نہ کرے کہ اس کے مقابلہ میں نہ ماں باپ کی محبت ٹھہر سکے.نہ بیٹوں کی محبت ٹھہر سکے.نہ بھائیوں کی محبت ٹھہر سکے.نہ بیویوں کی محبت ٹھہر سکے نہ قبیلہ اور قوم کی محبت ٹھہر سکے.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ثَلَا ثٌ مَنْ کُنَّ فِیْہِ وَجَدَ حَلَاوَۃَ الْاِیْمَانِ اَنْ یَکُوْنَ اللّٰہُ وَ رَسُوْلُہٗ اَحَبَّ اِلَیْہِ مِـمَّا سِوَاھُمَا وَاَنْ یُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا یُحِبُّہٗ اِلَّا لِلّٰہِ وَاَنْ یَکْرَہَ اَنْ یَعُوْدَ فِی الْکُفْرِ کَمَا یَکْرَہُ اَنْ یُقْذَ فَ فِی النَّارِ(بخاری کتاب الایمان باب حلاوۃ الایمان) یعنی جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں اس کے متعلق سمجھ لو کہ اُسے حلاوتِ ایمان حاصل ہوگئی ہے.اول یہ کہ خدا اور اس کا رسول اس کی نگاہ میں تمام ماسوا سے زیادہ محبوب ہو.دوم انسان دوسرے سے محض اللہ کے لئے محبت کرے سوم.ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی طرف لَوٹنا ایسا ہی ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالا جانا.وَ لَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آج تو یہ لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں اور بتوں کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دے رہے ہیں لیکن اگر یہی لوگ اس وقت کا نظارہ اپنے ذہنوں میں لا سکیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں سب کچھ بھول جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا کوئی معمولی گناہ نہیں.اس وقت تو یہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں لیکن اگر یہ اُس وقت کا تصور کر سکیں جب ان پر اپنے معبودوں کی بے بضاعتی روشن ہو جائےگی تو وہ ایسا کبھی نہ کریں جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اُن کے معبود اُن کے کسی کام نہ آئے بلکہ وہ توڑ پھوڑ کر پھینک دیئے گئے اور بیت اللہ کو خدائے واحد کی عبادت کے لئے پاک کر دیا گیا.اِذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ کی تشریح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اس اُخروی عذاب کی بھی تفصیل بیان فرمائی ہے جو کفار کو ملے گا اور بتایا ہے کہ انہیں تمثیلی طور پر سانپ اور بچھو اور اسی قسم کی اور خوفناک چیزیں نظر آئیں گی(مسند احمد بن حنبل مسند عبد اللہ بن عمر الجز ۱۰ صفحہ ۴۸۰).جو درحقیقت انہی کے اعمال کی ایک شکل ہوںگی کیونکہ دنیا میں انہوں نے سانپوں کی طرح لوگوں کو ڈسا اور بچھوئوں کی طرف نیش زنی سے کام لیا اور درندوں کی طرح لوگوں کو
Page 106
چیرا پھاڑا.اس لئے خدا تعالیٰ ان کی سزا کے لئے سانپوں اور بچھوئوں کو ہی اُن پر مسلّط کر دےگا اور انہیں اپنے اعمال کی سزا دےگا.یہ آیت اپنے مضمون کے لحاظ سے پہلی آیت سے نہایت گہرا تعلق رکھتی ہے.بلکہ درحقیقت یہ دونوں آیات ایک ہی مضمون کی حامل ہیں.اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ باوجود ان دلائل کے جو حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں اور باوجود اس کے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت دے رہا ہے اور باوجود اس کے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی تقدیر خاص کو بھی دیکھ رہے ہیں جو مومنوں کے حق میں جاری ہے پھر بھی یہ لوگ خدا تعالیٰ کے نِدّ قرار دے رہے ہیں اور ان سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں.اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَ رَاَوُا الْعَذَابَ (اور کاش کہ وہ لوگ اس وقت کو دیکھ لیتے)جب وہ لوگ جن کی فرمانبرداری کی جاتی تھی ان لوگوں سے جو فرمانبردار وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ۰۰۱۶۷ تھے الگ ہو جا ئیں گے اور عذاب کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھ لیں گے.اور ان کے (شرک کی وجہ سے نجات کے) سب ذریعے منقطع ہو جائیں گے.حلّ لُغات.تَبَرَّأَ باب تَفَعُّلْ سے ماضی کا صیغہ ہے اور اس کے معنے ہیں تَخَلَّصَ یعنی اُس نے چھٹکارا حاصل کر لیا(اقرب) اور اَلتَّبَرِّیْ (مصدر) کے معنے ہیں اَلتَّغَصِّی مِـمَّا یُکْرَ ہُ مُـجَاوَرَتُہٗ یعنی ناپسندیدہ چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا(مفردات) پس آیت کے معنے یہ ہیں کہ وہ معبودان باطلہ یا وہ ہستیاں جنہیں خدا تعالیٰ کا شریک قرار دیا جاتا ہے عبادت کرنے والوں کو ناپسندیدہ قرار دیںگے.اور اپنے آپ کو پاک ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو ایسے اعمال کرنے والوں کے ساتھ نہ تھے.اَ لْاَسْبَابُ سَبَبٌ کی جمع ہے اور اَلسَّبَبُ کے معنے ہیں مَایُتَوَ صَّلُ بِہٖ اِلٰی غَیْرِہٖ.وہ چیز جس کے ذریعہ سے غیر تک پہنچا جائے.اسی طرح اس کے معنے رستہ.محبت اور قرابت کے بھی ہیں.(لسان العرب) تفسیر.فرماتا ہے ایک زمانہ ایسا آئےگا کہ جن کو یہ لوگ نِدّ قرار دیتے ہیں وہ بھی اس وقت کہہ اُٹھیں
Page 107
گے کہ خدایا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہ تھا.اور اس طرح ان سے اپنی برأت اور نفرت کا اظہار کریںگے اور خدائی عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے.وَتَقَطَّعَتْ بِھِمُ الْاَسْبَابُ.اور ان کی نجات کے تمام ذرائع منقطع ہو جائیں گے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ باء بمعنے عَنْ بھی آتی ہے اور باء بمعنے سبب بھی آتی ہے.اور باء تعدیہ کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے یعنی فعل لازم کو متعدی بنانے کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے.پہلی صورت میں عَنْ کے مفہوم کو مدِّنظر رکھتے ہوئے اس آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ ان کے اسباب ان سے کٹ جائیں گے یعنی وہ چیزیں جو ان کے پاس تھیں اور جن کی نسبت وہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہم ان کی وجہ سے خدا تعالیٰ تک پہنچ جائیںگے یا وہ قرابتیں اور محبتیں جو رشتہ داری کی وجہ سے انہیںحاصل تھیں وہ سب کی سب کٹ جائیںگی اور ان کے تمام سہارے جاتے رہیں گے.باء کے معنے سبب لینے کی صورت میں یہاں ایک محذوف ماننا پڑے گا اور عبارت یوں ہو گئی کہ وَتَقَطَّعَتْ بِسَبَبِ کُفْرِ ھِمُ الْاَسْبَابُ کہ ان کے کفر کی وجہ سے اُن کے تمام ذرائع کامیابی جاتے رہیں گے.اور وہ تباہ ہو جائیںگے.تیسری صورت میں اس کا یہ مطلب ہو گا کہ جن چیزوں کو وہ خدا تعالیٰ کے وصال کا ذریعہ قرار دیتے ہیں یا وہ ذرائع جن کو وہ خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا سمجھتے ہیں وہی ان کو کاٹ دیں گے اور ان کی تباہی کا موجب بن جائیںگے.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیْلِہٖ (الانعام: ۱۵۴) کہ تم مختلف راستوں کے پیچھے نہ پڑو.ورنہ وہ تمہیں صحیح راستہ سے منحرف کر دیںگے اور تمہیں ادھر اُدھر لے جا کر تباہ کر دیںگے.وَ قَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا اور جو لوگ (ائمہ کفر کے) فرمانبردار تھے کہیں گے کہ کاش ! ہمیں ایک دفعہ (پھر دنیا میں ) واپس جانا (نصیب )ہوتا تَبَرَّءُوْا مِنَّا١ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ تو ہم بھی ان (ائمہ کفر) سے الگ ہو جاتے جس طرح (آج) یہ ہم سے الگ ہو گئے.اس طرح اللہ انہیں بتائے گا
Page 108
عَلَيْهِمْ١ؕ وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِؒ۰۰۱۶۸ کہ ان کےاعمال (کا نتیجہ چند) حسرتیں ہیں(جو) ان (ہی) پر( وبال ہوکر پڑیں گی )اور وہ (دوزخ کی) آگ سےہرگز نہیں نکل سکیں گے.حل لغات.کَرَّۃً اَلْکَرَّۃُ بِالْفَتْحِ اَلْمَرَّۃُ یعنی کرۃ کے معنے ایک دفعہ کے ہیں (اقرب) اَلْکَرُّ (مصدر) اَلْعَطْفُ عَلَی الشَّیْءِ کسی چیز کی طرف لَوٹنا(مفردات)پس آیت کے معنے یہ ہوںگے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ اور لَوٹنے کا موقعہ مل جائے.تفسیر.فرمایا اس دنیا میں تو تم خدا تعالیٰ کے شریک بناتے اور اس کے نِدّ قرار دیتے ہو مگر وہاں جا کر تمہارا یہ حال ہو گا کہ تم واپس اس دنیا میں آنے کی خواہش کرو گے اور کہو گے کہ ہم تو خیال کرتے تھے کہ یہ معبود ہمارے کام آئیںگے مگر انہوں نے تو موقعہ پر آکر دھوکا دے دیا.اس لئے ہمیں ایک بار پھر دنیا میںلَوٹا یا جائے تاکہ ہم بھی اُن سے ایسا ہی بے وفائی کا سلوک کرسکیں.كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ فرماتا ہے ہم اُن کے اعمال انہیں اس حال میں دکھائیں گے کہ وہ حَسَرَاتٍ ہوںگے.یعنی وہ اعمال انہیں حسرتیں ہی حسرتیں نظر آئیں گے اور وہ حسرتیں ایسی ہوںگی کہ جن کا وبال انہیں پر پڑےگا بعض حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا غیروں پر اثر پڑتا ہے مگر فرماتا ہے وہ ایسی حسرتیں ہوںگی جن کا اثر خود انہیں پر پڑے گا دوسروں پر نہیں.اس جگہ اگر حَسَرَاتٍ کو حال قرار دیا جائے تو رأی سے مراد رئویت عینی ہو گی اور اگر حَسَرَاتٍ کو مفعول قرار دیا جائے تو رؤیت قلبی مراد ہو گی اور معنے یہ ہوںگے کہ وہ خدا تعالیٰ سے کہیں گے کہ اگر ہمیں مبلّغ بنا کر دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم وہاں جاکر شوربرپا کر دیں گے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں.وَ مَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ دوزخی آگ سے نکالے نہیں جائیں گے کیونکہ اس جگہ خدا تعالیٰ کے سلوک کا ذکر نہیں بلکہ ان کی اپنی کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ خود اپنی ذاتی جدوجہد اور کوشش سے اس میں سے نکل نہیں سکیں گے اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے اگر ہم کہیں کہ بیمار ایک قدم بھی نہیں چل سکتا اور پھر اسے دوسرے دن ہسپتال لے جایا جائے تو کوئی شخص یہ نہیں کہےگا کہ کل تو تم نے یہ کہا تھا کہ بیمار ایک قدم بھی نہیں چل سکتا اور آج تم اسے ہسپتال داخل کر آئے ہو.کیونکہ ہمارایہ مطلب نہیں تھا کہ غیر بھی اُسے وہاں نہیں لے جاسکتے اسی طرح اس آیت میں جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود دوزخ سے نہیں نکل سکیں گے.یعنی اگر وہ
Page 109
اپنے زور کے ساتھ نکلنا چاہیںگے تو نہیں نکل سکیں گے چنانچہ اس کی وضاحت قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہو جاتی ہے کہ کُلَّمَآ اَرَادُوْآ اَنْ یَّخْرُجُوْامِنْھَآ اُعِیْدُوْا فِیْھَا وَقِیْلَ لَھُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِیْ کُنْتُمْ بِہٖ تُکَذِّبُوْنَ (السجدۃ: ۲۱) یعنی جب کبھی وہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریںگے تو پھر اُسی کی طرف لَوٹا دیئے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اب دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو تم جھٹلا یا کرتے تھے.پس اس جگہ جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اس عذاب سے نکل نہیں سکیں گے.یہ نہیں کہا گیا کہ خدا تعالیٰ بھی انہیں دوزخ سے نہیں نکالے گا اور انہیں دائمی عذاب میں مبتلا رکھے گا.دراصل اس بارہ میں بھی مومنوں اور کافروں میں بہت بڑا فرق رکھا گیا ہے.مومنوں کے لئے تو جنّت حق قرار دیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبۃ: ۱۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال اس وعدہ کے ساتھ خرید لئے ہیں کہ ان کو جنّت ملے گی گویا یہ ایک سودا ہے جو ان کا خدا تعالیٰ سے ہو چکا.یوں تو کسی کا بھی خدا تعالیٰ پر کوئی ذاتی حق نہیں مگر جس حق کو خدا تعالیٰ خود تسلیم کرلے وہ تو حق ہی سمجھا جائےگا.مگر کافروں کے لئے فرمایا کہ اگر وہ دوزخ کی تکالیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے.عربی زبان میں جو باء تاکید کے لئے آتی ہے اس کے معنے ہرگز کے ہوتے ہیں.پس اس جگہ وَمَا ھُمْ بِخٰرِجِیْنَ مِنَ النَّارِ میں تاکید کے معنے پائے جاتے ہیں.یعنی وہ اپنی ذاتی جد و جہد کے ساتھ جہنم میں سے ہرگز نکل نہیں سکیں گے.ہاں جب خدا تعالیٰ چاہے گا تو انہیں دوزخ سے نکال لے گا.جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کہ اُس میں کوئی بھی نہیں رہے گا اور ہوا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی.(کنز العمال کتاب القیٰمة ذکر النار وصفتھا) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا١ۖٞ وَّ لَا اے لوگو! جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے (اسے) کھاؤ.اور تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ١ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۰۰۱۶۹ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو یقیناً وہ تمہارا کھلا (کھلا )دشمن ہے.حل لغات.طَیّبًا طَابَ سے صفت مشبّہ ہے اور طَیِّبٌ کے معنے ہیں اَلْحَلَالُ حلال.اور جب
Page 110
مَالٌ طَیِّبٌ کہا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں ایسا مال جو شرعی لحاظ سے حلا ل ہو.(اقرب) پھر لکھا ہے وَاَصْلُ الطَّیِّبِ مَاتَسْتَلِذُّہُ الْحَوَاسُ وَمَا تَسْتَلِذُّہُ النَّفْسُ(مفردات).اور درحقیقت طیّب اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسانی حواس لذیذ قرار دیں اور جس سے انسان کا دل لطف اندوز ہو.پس آیت کے یہ معنے ہوںگے کہ ایسی چیزیں کھائو جو شرعی لحاظ سے حلال ہوں اور ظاہری لحاظ سے بھی تم انہیں لذیذ اور پسندیدہ سمجھو.خُطُوَاتٌکے معنے ہیں طُرُقٌ وَسُبُلٌ رستے اور طریق.اس کا مفرد خُطْوَ ۃٌ ہے جس کے معنے مَا بَیْنَ الْقَدَمَیْنِ کے ہیں یعنی دو قدموں کے درمیان کی جگہ اور فاصلہ.(اقرب) تفسیر.اس رکوع سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی پیشگوئی کے اس دوسرے پہلو کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ یُعَلِّمُھُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۃَ یعنی وہ نبی انہیں شریعت اور اس کے اسرار سے آگاہ کر ے گا.چنانچہ اس سلسلہ میں قرآن مجید نے سب سے پہلے حلال اور طیّب کھانے کی تعلیم کو لیا ہے.کیونکہ انسانی اعمال اس کی ذہنی حالت کے تابع ہوتے ہیں اور ذہنی حالت غذا سے متاثر ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو! جو کچھ زمین میں ہے اُس میں سے حلال اور طیّب اشیاء کا استعمال کرو.یعنی تم صرف یہی نہ دیکھا کرو کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا نہیں بلکہ یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ وہ طیّب بھی ہے یا نہیں اگر کسی چیز کا کھانا تمہارے مناسب حال نہ ہو خواہ اس لحاظ سے کہ وہ تمہاری صحت کے لئے مضر ہو یا اس لحاظ سے کہ ملکی اور قومی حالات کی وجہ سے تمہیں اس کے کھانے کی عادت نہ ہو یا اس وجہ سے کہ تمہاری طبیعت اس سے انقباض محسوس کرتی ہو تو تم محض یہ دیکھ کر کہ شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہے اسے مت کھائو.کیونکہ تمہارے لئے کھانے میں صرف حرام و حلال کا امتیاز مدِّنظر رکھنا ہی ضروری نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ تم ایسی چیزوں کا انتخاب کیا کرو جو تمہاری طبیعت اور تمہارے ماحول اور تمہارے معمول کے مطابق ہوں اور جن کا کوئی مضر اثر تم پر پڑنے کا امکان نہ ہو.مثلاً نزلہ اور زکام اور کھانسی میں تُرش اشیاء کا استعمال کھانسی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے اب اگر کوئی شخص کھانسی میں تُرش میوے استعمال کرتا ہے یا اسہال میں گوشت روٹی استعمال کرتاہے یا جگر کی خرابی میں قابض اور نفاخ غذائوں کا استعمال کرتا ہے توخواہ یہ چیزیں حلال ہی کیوں نہ ہوں اس وجہ سے کہ وہ اس کے لئے طیّب نہیں ہیں ان کا استعمال اسے نقصان پہنچائےگا پس اس جگہ طیّب کو حلال کے ساتھ لگا کر یہ بتایا ہے کہ صرف حلال کھانا ہی مومن کا کام نہیں بلکہ یہ دیکھنا بھی اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز طیّب ہو یعنی گندی اور سڑی ہوئی نہ ہو.مضر صحت نہ ہو.جو ساتھ کھانا کھانے والے لوگ ہوں ان کی طبائع کے خلاف نہ ہو.
Page 111
وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ.اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو.یعنی ایسا نہ کرو کہ جس طرف شیطان جا رہا ہے اُسی طرف تم بھی چلنا شروع کر دو.وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن سے ہمیشہ دُور رہنا چاہیے نہ کہ اُس کی پیروی کرنی چاہیے.کھانے پینے کے ذکر کے بعد شیطان کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اگر تم حلال اور پھر حلال میں سے بھی طیّب رزق چھوڑ دو گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ تم شیطان کے پیچھے چل پڑوگے کیونکہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس سے جسم تیار ہوتا ہے اور ناجائز یا مضر اشیاء کے استعمال سے تیار شدہ جسم یقیناً انسان کو بدی کی طرف لے جائےگا نیکی کی طرف نہیں لے جا سکتا.اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ الْفَحْشَآءِ وَ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ وہ تمہیں صرف بدی اور بے حیائی اور اس (بات) کی کہ تم اللہ (تعالیٰ ) کے متعلق جھوٹ باندھ کر وہ بات کہو مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۰۰۱۷۰ جو تم نہیں جانتے تلقین کرتا ہے.حل لغات.اِنَّمَا ( اِنَّ کے ساتھ مَا زائدہ ہے) لغت میں لکھا ہے اِذَا اُدْخِلَ عَلَیْہِ مَا یَبْطُلُ عَمَلُہٗ وَیَقْتَضِیْ اِثْبَاتَ الْحُکْمِ وَصَرْ فِہٖ عَمَّا عَدَاہُ.جب اِنَّ پر مَا داخل ہو جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے اور بعد میں مذکور چیز کے لئے کسی بات کو ثابت کرنے اور باقی (غیر مذکور) چیزوں سے اس بات کی نفی کرنے کا مقتضی ہوتا ہے.(مفردات) اَلسُّوْءُ کُلُّ مَا یُغَمُّ الْاِنْسَانَ مِنَ الْاُمُوْرِ الدُّنْیَوِیَّۃِ وَالْاُخْرَوِیَّۃِ وَمِنَ الْاَ حْوَالِ النَّفْسِیَّۃِ وَالْبَدَنِیَّۃِ وَالْخَارِجِیَّۃِ (مفردات).یعنی اَلسُّوْءُ سے مراد وہ تمام غمزدہ کر دینے والی تکالیف ہیں جو انسان کو دنیوی اور اُخروی امور نیز رُوحانی اور جسمانی اور دوسرے حالات کی وجہ سے زندگی میں پیش آتی ہیں.اَلْفَحْشَآءُ اَلْفَحْشَاءُ وَالْفَاحِشَۃُ مَایَشْتَدُّ قُبْحُہٗ مِنَ الذُّنُوْبِ.وَالْبُخْلُ فِیْ اَدَاءِ الزَّ کٰوۃِ وَقِیْلَ کُلُّ مَا نَھَی اللّٰہُ عَنْہُ (اقرب).یعنی فَحْشَاء اور فَاحِشَۃ سے مراد سخت بُرائی والا گناہ.زکوٰۃ کی ادائیگی میںبخل کرنا.اور بعض کے نزدیک ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو.
Page 112
اَلْفُحْشُ وَالْفَحْشَاءُ وَالْفَاحِشَۃُ مَا عَظُمَ قُبْحُہٗ مِنَ الْاَ فْعَالِ وَالْاَ قْوَالِ.فحش.فحشاء اور فاحشہ سے ہر ایسا قول یا فعل مراد ہے جو بہت ہی بُرا ہو.(مفردات) تفسیر.شیطان کے پیچھے چلنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر انسان کو مختلف قسم کی بُرائیوں میں مبتلا کر دیتا ہے جیسے بدظنی ہے یا جھوٹ ہے یا کینہ ہے یا جہالت ہے یا سُستی اور غفلت ہے یا بُزدلی ہے یا تکبر ہے یا بے غیرتی ہے یا ناشکری ہے یہ وہ بُرائیاں ہیں جن سے صرف انسان کی اپنی ذات کو نقصان پہنچتا ہے اور جن کی طرف سوء کے لفظ میں اشارہ کیا گیا ہے.لیکن جب انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا تو دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فحشاء یعنی ایسی بدیاں کرواتا ہے جن کا دوسرے لوگوں پر بھی اثر پڑتا ہے جیسے خیانت اور تہمت اور ظلم اور دھوکا اور قتل اور چوری اور مارپیٹ اور گالی اور ناواجب طرف داری اور رشوت وغیرہ ایسے جرائم ہیں جو دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں پھر وہ بدیوں میں اور زیادہ بڑھاتا ہے اور آخر انسان کو خدا کے مقابلہ میں کھڑا کر دیتا ہے یا انسان کے اندر ایسی بے حیائی پیدا کر دیتا ہے کہ اُسے دوسروں کے سامنے بھی برائیوں کے ارتکاب میں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا.اور وہ بر ملا خدائی احکام کے خلاف لب کشائی شروع کر دیتا ہے یا اُس پر افتراء پردازی شروع کر دیتا ہے.گویا پہلے تو وہ ایسی بدیاں کرواتا ہے جن کا ضرر صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے.پھر غیرتِ انسانی مٹتی ہے تو ایسی بدیاں کرواتا ہے جن سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں.پھر اور ترقی کر کے اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلواتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ہتک کرنے والی اور اس کا مضحکہ اڑانے والی ہوتی ہیں.اور اس طرح وہ درجہ بدرجہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے.غرض شیطان کبھی یکدم بڑے گناہ پر انسان کو آمادہ نہیں کرتا.بلکہ اس کے وساوس کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ وہ پہلے چھوٹی بدی کا حکم دیتا ہے پھر بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے.اور پھر خدا پر جھوٹ باندھنے کے لئے تیار کر دیتا ہے.گویا چھوٹی نافرمانی سے شروع کر کے اُسے انتہا تک لے جاتا ہے.وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس (کلام) کی جو اللہ نے اتارا ہے پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ (نہیں) ہم تو اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا١ؕ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ اسی (طریقہ ) کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا.بھلا اگر ان کے باپ دادے کچھ بھی عقل
Page 113
شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ۰۰۱۷۱ نہ رکھتے اور نہ راہ راست پر چلتے ہوں (تو پھر بھی وہ ایسا ہی کریں گے).تفسیر.اس آیت میں بتایا کہ شیطان کی پیروی کرنے کا ایک یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر لوگوں کو خدا تعالیٰ کی بات ماننے کے لئے کہا جائے تو ان کی عقل ایسی ماری جاتی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے اور اُنہیں کے پیچھے چلیں گے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ ٔنبوت فرمایا تو مکہ والوں نے آپ کا شدیدمقابلہ کیا.وہ لوگ آخر کیوں مقابلہ کرتے تھے اس لئے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس مذہب کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے آبائو اجداد قائم تھے.گویا وہ کسی چیز کے ذاتی حُسن کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ صرف حسنِ اضافی اُن کے پیش نظر تھا اور باوجود اس کے کہ وہ جاہلانہ باتیں تھیں اُن لوگوں نے ان کے لئے اپنا مال اور اپنے عزیزوں اور اقرباء تک قربان کر دیئے تاکہ وہ چیزیں جو ان کی ہیں بچ جائیں.اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا بیوقوف ہوں تو کیا پھر بھی تم وہی کچھ کرو گے جو وہ کرتے چلے آئے ہیں یعنی تمہارے باپ دادا تو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے کیا تم بھی ان کے نقشِ قدم پر چل کر تباہ ہونا چاہتے ہو.ہمارے سلسلہ میں بھی لوگوں کے داخل ہونے میں سب سے بڑی روک یہی ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا وہ باتیں جنہیں پہلے لوگ سالہا سال سے مانتے چلے آئیں ہیں ہم انہیں چھوڑدیں یہ تو بڑی مشکل بات ہے.غرض اس آیت میں مخالفین اسلام کا سب سے بڑا اعتراض یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم تو اسی طریق کی پیروی کریںگے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا اس جگہ قَالُوْا سے یہ مراد نہیں کہ وہ منہ سے بھی ایسا کہتے ہیں.بہت لوگ منہ سے بھی کہتے ہیں لیکن بہت ہیں جو منہ سے نہیں کہتے مگر پھر بھی ان کے انکار کی وجہ یہی ہوتی ہے.اور قول کا لفظ ان معنوں میں عربی زبان میں استعمال ہو جاتا ہے.جیسے کہتے ہیں اِمْتَـلَأَ الْحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِیْ (اقرب)یعنی حوض بھر گیا اور اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ بس بس.اس آیت میں بھی اسی محاورہ کے مطابق قول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ مخالفین اسلام کے اس اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اتنا تو سوچیں کہ اگر اُن کے باپ دادے ایسے ہوں کہ وہ کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ راہ راست پر ہوں تو کیا پھر بھی وہ ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے یعنی کسی کی اتباع دو ہی طرح ہوتی ہے یا تو وہ بڑا عقلمند ہو اور یا پھر خدا تعالیٰ سے اُس نے ہدایت پائی ہوئی ہو.لیکن اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کیا پھر بھی اُس کی اِتباع کی جاتی ہے؟ اور تمہارے باپ دادوں
Page 114
کی تعلیم ان دونوں امور سے خالی ہے.نہ عقل کے مقابلہ میں ٹھہرتی ہے اور نہ آسمانی شہادت اُس کی تائید میں ہے.یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا سے دین کے بارے میں تو اختلاف نہیں کرنا چاہتے لیکن دنیوی امور کے بارہ میں وہ روزانہ اُن سے اختلاف کرتے ہیں.ہزار ہا مثالیں اس امر کی پائی جاتی ہیں کہ دنیوی امور میں لوگوں نے اپنے باپ دادا کی اقتداء نہیں کی بلکہ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ اُن کا فائدہ کس امر میں ہے.وہ روزانہ ریلوں میں چڑھتے ہیں اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا تو گدھوں پر سوار ہوتے تھے ہم ریل گاڑیوں پر کیوں سوار ہوں؟ اسی طرح عقلی اور علمی باتوں میں ان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ نئی روشنی کے علوم سے فائدہ اُٹھاتے اور ان کے پیچھے چلتے ہیں.مگر دین کا معاملہ ہو تو ان کے باپ دادے بڑے عقلمند بن جاتے ہیں.حالانکہ خود اُن کا عمل اس طریق کے خلاف گواہی دے رہا ہوتا ہے مگر ایسی صاف اور موٹی بات بھی جب ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے اور صداقت سے منہ پھیر لیتے ہیں.وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اور ان لوگوں کا حال جنہوں نے کفر کیا ہے اس شخص کے حال کے مشابہ ہے جو اس چیز کو پکارتا ہے جو سوائے پکاراور اِلَّا دُعَآءً وَّ نِدَآءً١ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۰۰۱۷۲ آواز کے کچھ نہیں سنتی.(یہ لوگ) بہرے گونگے اور اندھے ہیں اس لئے سمجھتے نہیں.حلّ لُغات.یَنْعِقُ نَعَقَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور نَعَقَ الرَّاعِیْ بِغَنَمِہٖ کے معنے ہیں صَاحَ بِھَا وَ زَجَرَھَا.چروا ہے نے اپنی بکریوں کو آواز دی اور اُن کو ڈانٹا.اور جب نَعَقَ الْغُرَابُ کہیں تو معنے ہوںگے صَاحَ کوّے نے کائیں کائیں کی.اور نَعَقَ الْمُؤَذِّنُ کے معنے ہیں رَفَعَ صَوْتَہٗ بِا لْاَ ذَانِ.مؤذن نے اذان کے لئے اپنی آواز بلند کی.(اقرب) نِدَآءٌ اَلنِّدَاءُ کے معنے ہیں رَفْعُ الصَّوْتِ وَ ظُھُوْرُ ہٗ.آواز کا بلند اور واضح ہونا.(اقرب) تفسیر.زیرتفسیر آیت ایک تمثیلِ مرکب ہے جس میں حذفِ مضاف سے کام لیا گیا ہے اور دَاعِی کا لفظ اس میں محذوف ہے.یعنی اصل عبارت یوں ہے کہ مَثَلُ دَاعِی الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کَمَثَلِ الَّذِیْ یَنْعِقُ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار کے داعی ہیں.آپ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو جانوروں کو اپنی طرف بلانے
Page 115
کے لئے آواز دیتا ہے.مگر وہ جانور اُس کی آواز کے سوا اور کچھ نہیں سُنتے گویا یہ کفار بھی رات اور دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سُنتے ہیں اور صبح و شام انہیں وحی الہٰی سنائی جاتی ہے.ہر وقت ان کے کانوں میں نیکی اور تقویٰ اور خدا ترسی کی باتیں ڈالی جاتی ہیں مگر یہ لوگ جانوروں کی طرح الفاظ تو سنتے ہیں اور آواز تو ان کے کانوں میں پڑتی ہے لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور اپنی پُرانی ڈگر پر چلتے چلے جاتے ہیں.اس تمثیل میں بتایا گیا ہےکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لئے ایک داعی کے طور پر ہیں.اور کفار آپ کے لئے ریوڑ کی حیثیت رکھتے ہیں.آپؐ ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور آپؐ کی دُعا اور نداء بھی وہ سنتے ہیں مگر وہ جانوروں کی طرح اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے.گویا جانوروں کو بلانے والے کا سا حال ہمارے نبی کا ہوتا ہے کہ اس کی بات کو یہ لوگ سمجھتے نہیں.اس تشریح پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مشبّہ اور مشبّہ بہٖ کے کل اجزاء میں مطابقت ہونی ضروری ہوتی ہے مگر وہ یہاں موجودنہیں اس کا جواب یہ ہے کہ تمثیلِ مرکب میں مشبّہ اور مشبّہ بہٖ کے تمام افراد میں مطابقت نہیں دیکھی جاتی بلکہ صرف اتنی بات دیکھی جاتی ہے کہ آیا ان میں کسی خاص بات میں مشابہت پائی جاتی ہے یا نہیں اور اگر ہو تو تشبیہ درست سمجھی جاتی ہے.چنانچہ سیبویہ کا یہی قول ہے کہ مرکب تمثیل میں تمام اجزاء مشبّہ کا مشبّہ بہٖ کے اجزاء کے مطابق ہونا ضروری نہیں بلکہ اس کے صرف بعض اجزاء کی مطابقت ہی کافی سمجھی جاتی ہے.(املاء ما منّ بہِ الرَّحمٰن زیر آیت ھٰذا).ان معنوں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کفار کی مثال بھیڑ بکریوں کی سی ہے تو بھیڑ بکریاں تو داعی کی آواز سنتی ہیں اور کفار بھی سُنتے ہیں پھر اُن کو صُمٌّ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صُمٌّ سے یہاں یہ مراد نہیں کہ وہ جسمانی طور پر بہرے ہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ ان کے کان حق بات سننے سے قاصر ہیں اور صُمٌّ کے بعدبُکْمٌ اور عُمْیٌ کا لفظ اس مفہوم کی وضاحت کرتا ہے کیونکہ جس طرح بُکْمٌ کے یہ معنے ہیں کہ وہ حق بات کہہ نہیں سکتے اورعُمْیٌ کے یہ معنے ہیں کہ وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے.اسی طرح صُمٌّ سے مراد یہ ہے کہ وہ حق بات کو سن نہیں سکتے گویا وہ آواز تو سنتے ہیں لیکن اس کی حقیقت نہیں سمجھتے اور نہ اس کے مطابق اپنے اندر تغیر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں.پس جہاں سُننے کا ذکر ہے وہاں یہ مراد ہے کہ وہ صرف الفاظ سُنتے ہیں اور جہاں نہ سُننے کا ذکر ہے وہاں حقیقت کا سُننا مراد ہے اور حقیقت کے سمجھنے کی نفی سے دُعا اور نداء کے سننے کی نفی نہیں ہو سکتی.اور یا پھر صُمٌّ سے ایسے لوگ مراد ہیں جن سے کسی فائدہ کی امید نہ کی جاتی ہو کہ یہ معنے بھی لُغتاً ثابت ہیں چنانچہ اقرب الموارد جو لُغت کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے اَ لْاَصَمُّ اَیْضًا اَلرَّجُلُ لَا یُطْمَعُ فِیْہِ یعنی ایسے شخص کو بھی اَصَم کہتے ہیں جس سے کسی بھلائی کی اُمید نہ کی جا سکے.
Page 116
دوسرؔے معنے اس کے یہ ہیں کہ ان کفار کی مثال جانوروں کی طرح ہے جن کو بلانے والا اپنی طرف بلاتا ہے اور جانور بلانے والے کی آواز سُن کر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں.گو اس کے الفاظ کا مطلب اور مفہوم نہیں سمجھتے اسی طرح یہ لوگ بھیڑ چال کے طور پر ایک دوسرے کی اتباع کرتے ہیں اوریہ کبھی غور نہیں کرتے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے اور آیا اس پر عمل کرنا ان کے لئے مفید ہے یا مضر؟ وہ صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سردار یا ہمارے لیڈر نے فلاں بات کہی ہے یا ہماری قوم یا برادری ایسا کہتی ہے.اس کے بعد وہ اپنی عقل و فہم اور تدبّرکے تمام دروازے بند کر لیتے ہیں اور اندھا دھند اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں.پس ان کی مثال جانوروں کی سی ہے کہ دوسرے کی بات سن کر یہ لوگ اس پر غور کرنے کے عادی نہیں بلکہ اندھی تقلید کے خوگر ہیں.گویا ان کے کان بھی ہیں مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ انہیں جس طرف بلایا جا رہا ہے وہ ہلاکت اور بربادی کی جگہ ہے یا امن اور سلامتی کا مقام ہے.ان کی زبانیں بھی ہیں مگر دلیری سے حق بات کہنے کی جرأت کھو بیٹھی ہیں اور ان کی آنکھیں بھی ہیں مگر سلامتی کی راہ ان کو دکھائی نہیں دیتی.تیسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ ان کفار کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو چیختا اور چلاتا اور بتوں کو اپنی مدد کے لئے بلاتا ہے اور اس کا بلانا دو طرح ہے ایک دعا کے ذریعہ سے دوسرا نداء کے ذریعہ سے.نداء ایسی آواز کو کہتے ہیں جو سنی جائے یا نہ سُنی جائے اور دعا اس آواز کو کہتے ہیں جو سنی جائے.فرماتا ہے وہ ُبت جن کو یہ لوگ اپنی مد دکے لئے پکارتے ہیں.وہ نہ ان کی دُعا سنتے ہیں نہ نداء.گویا ان کفار کا کام محض دعا اور نداء ہی ہے ورنہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیںسُنتے.نہ دُعا سنتے ہیں نہ نداء سنتے ہیں.اس لئے اُن کے بلانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا.اس صورت میں اِلَّا کو زائدہ تسلیم کرنا پڑے گا یا پھر یہ فقرہ اس طرح ہو گا کہ لَا یَسْمَعُ اِلَّا ھُوَ یَدْعُوْا دُعَاءً وَ نِدَاءً.یعنی وہ بُت تو کچھ نہیں سنتے مگر وہ پکارنے والا برابر دُعائیں کئے چلا جاتا ہے اور آوازیں دیتا چلا جاتا ہے.ان معنوں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ چیختے چلاتے ہیں تو پھر وہ بُکْمٌ کیسے ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بُکْمٌ کے یہ معنے ہیں کہ وہ حقیقت کا اپنی زبان سے اقرار کرنے کے لحاظ سے گونگے ہیں.اور اس کی دلیل صُمٌّ اور عُـمْیٌ کے الفاظ ہیں جیسے صُمٌّ سے ایسے لوگ مراد ہیں جن کے کان حق بات کے سُننے سے بہرے ہیں اور عُمْیٌ سے مراد حق کو نہ دیکھنے والے لوگ ہیں اسی طرح بُکْمٌ سے مراد وہ لوگ ہیں جو روحانی نقطہ نگاہ سے گونگے ہیں.اور جو سچائی کا برملا اظہار کرنے سے قاصر رہتے ہیں.اگر یہاں صرف بُکْمٌ کا لفظ ہوتا تو اعتراض درست ہوتا.لیکن صُمٌّ اور عُمْیٌ کے الفاظ نے صحیح معنے واضح کر دیئے.ترتیب و ربط.اس آیت کا آیت ماقبل سے پہلے معنوں کے لحاظ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ
Page 117
نے فرمایا تھا وَاِذَا قِیْلَ لَھُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰہُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَیْنَا عَلَیْہِ اٰبَآءَ نَا کہ جب انہیں خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا اس کی اتباع کرو تو وہ اُسے سن کر اعراض اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اُسی طریق کی اتباع کریںگے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا.گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دعوتِ حق دینا ایسا ہی ہے جیسے جانوروں کو اپنی طرف بلانا.یہ لوگ بھی آپ کی آواز سُنتے ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ اس آواز پر لبیک کہنا کس قدر ضروری ہے اور وہ اپنے باپ دادا کے طریق پر چلتے چلے جاتے ہیں.دوسرے معنوں کے لحاظ سے اس آیت کا پہلی آیت سے یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنے کے تو بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کے باپ دادا اپنے ُبتوں کو پکارتے اور آوازیں دیتے تھک گئے اور کچھ بھی نتیجہ برآمد نہ ہوا.ایسی صورت میں ان کا یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کریںگے ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی ُبتوںکو بلائے اور اس کا بلانا بالکل بیکار ثابت ہو اور اُسے کوئی جواب نہ ملے پس ان لوگوں کا بھی اپنے ُبتوںکے سامنے چیخنا چلانا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا.يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ اےلوگوجو ایمان لائے ہو !ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ.اور اگر تم (واقعہ میں) اشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۰۰۱۷۳ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر(بھی ادا)کرو.تفسیر جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اسلامی شریعت نے صرف حلال چیزوں کے کھانے کا ہی حکم نہیں دیا بلکہ حلال میں سے بھی طیّب اشیاء کے استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور یہ اسلام کی ایسی امتیازی خصوصیت ہے جس میں کوئی اور مذہب اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا.اسی طرح اس نے حلال کے مقابلہ میں صرف حرام کا درجہ ہی نہیں رکھا بلکہ اس سے اُتر کر اس نے بعض چیزوں کو مکروہ بھی قرار دیا ہے اور مومنوں کے لئے ان کا استعمال ناپسند فرمایا ہے.گویا چار مختلف مدارج ہیں جن کو مدِّنظر رکھنا ضروری ہوتا ہے اوّل طیّب دوم حلال سوم حرام چہارم مکروہ.حلال ترقی کرتے کرتے طیّب تک پہنچ جاتا ہے اور حرام گرتے گرتے مکروہ تک آجاتا ہے.غرض اسلام اور دیگر مذاہب میں یہ
Page 118
فرق ہے کہ دوسرے مذاہب صرف حلال حرام تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اور اسلام حلال اور حرام کے علاوہ بعض چیزوں کو طیّب یا مکروہ بھی قرار دیتا ہے.اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کونسی چیزیں بعض حالات میں حلال ہو جاتی ہیںگو اصل میں حرام ہوں اور کون سی چیزیں بعض حالات میں حرام ہو جاتی ہیں گو اصل میں حلال ہوں اور اس طرح موازنہ اشیاء کو قائم کرتا اور ایک لطیف باب گناہ اور نیکی کے امتیاز کے لئے کھول دیتا ہے مثلاً ہماری شریعت میں لوگوں کو ایذاء دینے سے منع کیا گیا ہے.اب اگر حلال چیز سے کسی وقت دوسروں کو ایذاء پہنچ جائے تو اس وقت اس کا استعمال کرنا بھی حرام ہوجائےگا.جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم نے فرمایا کہ مَنْ اَکَلَ مِنْ ھٰذِہِ الشَّجَرِ یَعْنِی الثُّوْمَ فَلَا یَأْتِیَنَّ الْمَسَاجِدَ (مسلم کتاب المساجد باب نھی من أ کل ثومًا...).یعنی جو شخص کچے لہسن کا استعمال کرے اسے چاہیے کہ مسجد میں نہ آئے.ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے کہ فَاِنَّ الْمَلَائِکَۃَ تَتَأَذّٰی مِمَّایَتَأَذّٰی مِنْہُ الْاِنْسُ کہ ملائکہ بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں (مسلم کتاب المساجد باب نھی من أ کل ثومًا...).اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ باوجود اس کے کہ لہسن کھانا جائز ہے پھر بھی مساجد میں آنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز وغیرہ کا کھانا ممنوع قرار دے دیا.اور ایسے شخص کو نماز باجماعت سے بھی روک دیا.ورنہ نماز تو کسی صورت میں بھی چھوڑی نہیں جاسکتی وہ اگر مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا تو بہر حال اُسے گھر پر نماز پڑھنی پڑے گی.لیکن اس وجہ سے کہ وہ دوسروں کے لئے دُکھ اور تکلیف کا موجب نہ بنے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اجتماعی عبادت سے الگ رہے تاکہ مومنوں کو تکلیف نہ ہو.غرض یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے نہ صرف حلّت و حرمت کے مسائل بیان کئے بلکہ اس نے یہ بھی بتادیا ہے کہ کھانے کی چیزوں میں سے ادنیٰ درجہ حلال کاہے اور حرام چیزوں میں سے ادنیٰ درجہ کراہت کا ہے پس مومنوں کو حلال اور حرام پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ انہیں تقویٰ کی باریک راہیں اختیار کرتے ہوئے حلال میں سے بھی طیّب چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے اور حرام چیزیں تو الگ رہیں مکروہ چیزوں کے پاس پھٹکنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال کی بجائے صرف طیّب کا لفظ رکھا ہے جس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں خاص طور پر مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے یعنی اعلیٰ درجہ کے مومنوں کو.ورنہ اس رکوع کے شروع میں بھی يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا میں اَلنَّاسُ سے مراد مومن ہی تھے کیونکہ کفار کو قرآن کریم مسائل تفصیلی میں حکم نہیں دیتا.لیکن وہاں اَلنَّاسُسے ادنیٰ درجہ کے مومن مراد تھے جو طبعی خواہشات کی طرف جھکنے والے تھے.اسی لئے وہاں ان کی
Page 119
کمزوریوں کو مدِّنظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہكُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا یعنی جو کچھ حلال اور طیّب ہے کھائو.کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ صرف طیّبا ت تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھ سکتے بلکہ خالص حلّت و حرمت کے دائرہ کے اندر ہی رہنا چاہیں اور زیادہ پابندیاں اپنے لئے برداشت نہ کر سکیں لیکن یہاں خاص درجہ کے مومنوں کو مدِّنظر رکھتے ہوئے حکم دیا کہ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ تم صرف وہ طیبات استعمال کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں.یہی وجہ ہے کہ پہلے حکم کے نتیجہ میں فرمایا تھا کہ تم شیطان کے پیچھے چلنے سے بچ جائو گے لیکن یہاں یہ فرمایا کہ اگر تم صرف طیبات ہی استعمال کر و گے تو اس کے نتیجہ میں تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا سکو گے.یعنی تمہیں ایسے نیک اعمال کی توفیق ملے گی جو تمہاری روح کو اللہ تعالیٰ کے آستانہ کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے.جیسے دوسرے مقام پر وضاحتاً فرمایا کہيٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا (المؤمنون: ۵۲) یعنی اے ہمارے رسولو! تم طیبات کھائو اور مناسب حال اعمال بجا لائو.گویا اسلام نے انسانی اعمال اور اخلاق پر غذا کے اثرات کو واضح طور پر تسلیم فرمایا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس نقطہ کو ہمیشہ مدِّنظر رکھیں اور غذائی معاملات میں طیّبات کو ترجیح دیا کریں تاکہ ان کے اخلاق بھی متوازن رہیں اور ان میں ناواجب اونچ نیچ کا کوئی پہلو دکھائی نہ دے.غرض یہاں اعلیٰ درجہ کے ایمان کے مناسب حال كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ فرمایا.اور جب انسان طیبات پر حصر کرلےگا تو نہ صرف یہ کہ وہ منہیات سے بچ جائےگا بلکہ وہ صالحات کی بھی توفیق پائےگا.پس اعلیٰ درجہ کے مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر حلال بھی نہ کھائے بلکہ خاص طور پر طیّب کو مدنظر رکھے یا پھر اس آیت میں صرف طیب کو اس لئے بیان کر دیا کہ حلال اسی میں آجاتا ہے.اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ اس نے تم پر صرف مردار، خون، سؤر کے گوشت کو اور ان چیزوں کو جنہیں اللہ کے سوا کسی اور سے نامزد کردیا مَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ١ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ ہو حرام کر دیا ہے.مگر جو شخص (ان اشیاء کے استعمال پر) مجبور ہو جائے اور وہ نہ تو قانون کا مقابلہ کرنے والا ہو فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰۰۱۷۴ اور نہ حدود سے آگے نکلنے والا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں.اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.حل لغات.اَلْمَیْتَۃُ اَلْمَیْتَۃُ مَالَمْ تَلْحَقْہُ الزَّ کٰوۃُ.وَالْحَیَوَانُ الَّذِیْ یَمُوْتُ حَتْفَ اَنْفِہٖ (اقرب)
Page 120
اَلْمَیْتَۃُ مَیْتٌکامؤنث ہے.اور مَیْتَۃٌ سے مراد ہر ایسی چیز ہے جو بغیر کسی بیرونی سبب کے مرے اور اُسے ذبح نہ کیا جائے.اور شریعت اسلام کے نزدیک اُسے بھی مُردار ہی کہتے ہیں جو ذبح نہ ہو خواہ ایسا جانور خودبخود مر جائے یا کوئی دوسرا اُسے مار دے.دَمٌ کے معنے خون کے ہیں اور اس سے مراد دم ِمسفوح ہے جو ذبح کرنے سے بہہ جاتا ہے.اندر کا خون مراد نہیں.اُھِلَّ اَھَلَّ سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اَھَلَّ الْھِلَالُ وَاُھِلَّ (مجہولًا) کے معنے ہیں ہلال ظاہر ہو گیا (۲)اَھَلَّ الْقَوْمُ الْھِلَالَ رَفَعُوْا اَصْوَاتَھُمْ عِنْدَ رُؤْیَتِہٖ.لوگوں نے ہلال پر آواز بلند کی (چاند کو ہلال اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے دیکھنے پر آواز بلند کی جاتی ہے)(۳) اور اَھَلَّ الصَّبِیُّ ُّ کے معنے ہیں رَفَعَ صَوْتَہٗ بِالْبُکَاءِ یعنی بچہ رونے لگا.(۴) اور جب اَھَلَّ الرَّجُلُ کہیں تو معنے ہوںگے نَظَرَ اِلَی الْھِلَالِ آدمی نے ہلال دیکھا (۵) اور اَھَلَّ الشَّھْرُ کے معنے ہیں ظَھَرَ ھِلَا لُہٗ نئے مہینے کا ہلال نکلا (۶) اَھَلَّ السَّیْفُ بِفُلَانٍ کے معنے ہیں قَطَعَ فِیْہِ تلوار نے اُسے کاٹ دیا.(۷) اَھَلَّ الْعَطْشَانُ کے معنے ہیں رَفَعَ لِسَانَہٗ اِلٰی لُھَاتِہٖ لِیَجْتَمِعَ لَہٗ رِیْقُہٗ یعنی پیاسے نے اپنی زبان تھوک سے تر کرنے کے لئے حلق کے قریب کی.(۸) اَھَلَّ اللّٰہُ السِّحَابَ کے معنے ہیں خدا تعالیٰ نے بادل برسایا (۹) اَھَلَّ الشَّھْرَکے معنےہیں رَأَی الْھِلَالَ چاند دیکھا.(۱۰) اَھَلَّ ا لْمُلَبِیُّ کے معنے ہیں رفَعَ صَوْتَہٗ بِالتَّلْبِیَۃِ، یُقَالُ اَھَلَّ الْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَۃِ لَبّٰی وَرَفَعَ صَوْ تَہٗ.محرم نے حج اور عمرہ کے لئے تلبیہ کیا اور آواز بلند کی.(۱۱) اَھَلَّ فُلَانٌ بِذِکْرِ اللّٰہِ کے معنے ہیں رَفَعَ صَوْتَہٗ بِہٖ عِنْدَ نِعْمَۃٍ اَوْرُؤْیَۃِ شَیْءٍ یُعْجِبُہٗ فلاں شخص نے کوئی نعمت دیکھ کر ذکر الہٰی کے لئے اپنی آواز بلند کی (۱۲) اَھَلَّ بِالتَّسْمِیَۃِ عَلَی الذَّبِیْحَۃِ کے معنے ہیں قَالَ بِسْمِ اللّٰہِ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا.وَمَا اُھِلَّ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰہِ کے معنے ہیں نُوْدِیَ عَلَیْہِ بِغَیْرِ اسْمِ اللّٰہِ عِنْدَ ذَبْـحِہٖ.جو جانور خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے.(اقرب) اُضْطُرَّ ضَرَّ سے باب افتعال کا ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور اِضْطَرَّہٗ اِلَیْہِ کے معنے ہیں اَحْوَجَہٗ وَاَلْجَاہٗ فَاضْطُرَّ بِصِیْغَۃِ الْمَجْھُوْلِ اَیْ اُلْجِیءَ(اقرب) اضطرار کسی شخص کو ایسے کام پر مجبور کر دینے کو کہتے ہیں جو اس کے لئے باعث ضر ر ہو یا اُسے ناپسند ہو.یہ مجبوری خواہ بیرونی ہو جیسے تہد ید و تخویف یا اندرونی ہو جیسے قدرتی مطالبات اور طبعی حوائج یعنی بھوک وغیرہ.ان دونوں میں سے کسی قسم کی مجبوری کے ماتحت انسان کام کرے تو اُسے اضطرار کہتے ہیں.
Page 121
بَاغٍ بَغَیَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اَلْبَغْیُ کے معنے ہیں(ا) اَلظُّلْمُ ظلم (۲) اَلْجُرْمُ وَالْجِنَایَۃُ قصور (۳)اَلْعِصْیَانُ نافرمانی (۴) کُلُّ مُجَاوَزَۃٍ وَاِفْرَاطٍ عَلَی الْمِقْدَارِ الَّذِیْ ھُوَ حَدُّ الشَّیْءِ فَھُوَ بَغْیٌ کسی مقررہ حد سے تجاوز کرنا بھی بغی ہے.(اقرب) اور اَلْبَاغِی سے مراد ہے (۱) اَلطَّالِبُ چاہنے والا (۲) اَلظَّالِمُ ظالم (۳) وَاَلْعَاصِیْ عَلَی اللّٰہِ وَالنَّاسِ اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی مخالفت میں کھڑا ہوجائے.عَادٍ حدّ سے گذر جانے والا یعنی جو قانون پر عمل کرتے کرتے کچھ زیادتی یا کمی کر دے.اِثْمٌاس جگہ اس کے معنے سزا کے ہیں.سبب کو مسبب کی جگہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ سزا کا سبب گناہ ہوتا ہے.(۲) اِثْمٌ کے معنے گناہ کے بھی ہو سکتے ہیں.تفسیر.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ میں جن اشیاء کے کھانے سے منع کیا گیاہے.وہ دو قسم کی ہیں اول حرام دوم ممنوع.لُغۃً توحرام کا لفظ دونوں قسموں پر حاوی ہے.لیکن قرآن کریم نے اس آیت میں صرف چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے.یعنی ُمردار ، خون.سؤر کا گوشت اور وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام سے نامزد کر دیاگیا ہو.ان کے سوا بھی شریعت میں بعض اور چیزوں کے استعمال سے روکا گیا ہے.لیکن وہ چیزیں اشیاء ممنوعہ کی فہرست میں تو آئیں گی.قرآنی اصطلاح کے مطابق حرام نہیں ہوںگی.جیسے حضرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ نَھٰی عَنْ کُلِّ ذِیْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ کُلِّ ذِیْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ(مسلم کتاب الصّید والذبائح باب تحریم أکل کل ذی ناب من السباع...) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والے درندے اور پنجوں والے پرندے کو کھانا ممنوع قرار دیا ہے.اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ نَھٰی عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاِنْسِیَّۃِ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے.(مسلم کتاب الصید والذبائح باب تحریم أکل لحم الحمر الإنسیۃ ).یہ احکام اس آیت یا دوسری آیات کے مضمون کے مخالف نہیں ہیں.کیونکہ جس طرح اوامر کئی قسم کے ہیں بعض فرض ہیں بعض واجب ہیں اور بعض سنت ہیں.اسی طرح نہی بھی کئی اقسام کی ہے.ایک نہی محرّمہ ہے اور ایک نہی مانعہ ہے اور ایک نہی تنزیہی ہے.پس حرام چار اشیاء ہیں باقی ممنوع ہیں اور ان سے بھی زیادہ وہ ہیں جن کے متعلق نہی تنزیہی ہے.یعنی بہتر ہے کہ انسان اُن سے بچے.حرام اور ممنوع میں وہی نسبت ہے جو فرض اور واجب میں ہے.پس جن اشیاء کو قرآن کریم نے حرام کہا ہے ان کی حرمت زیادہ سخت ہے اور جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
Page 122
نے منع کیا ہے وہ حرمت میں ان سے نسبتاً کم ہیں اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے احکام میں ان کی مثال فرض اور واجب اور سنت کی سی ہے حرام تو بمنزلہ فرض کے ہے اور منع بمنزلہ واجب کے.جس طرح فرض اور واجب میں فرق ان کی سزائوں کے لحاظ سے کیا جاتا ہے اسی طرح جن اشیاء کی حرمت قرآن کریم میں آئی ہے اگر انسان اُن کو استعمال کرے گا تو اس کی سزا زیادہ سخت ہو گی اور جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کے استعمال سے اس سے کم درجہ کی سزا ملے گی لیکن بہر حال دونوں جرم قابل گرفت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوں گے.حرام فعل کا ارتکاب کرنے سے انسان کے ایمان پر اثر پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ لازماً بدی ہوتی ہے.لیکن دوسری چیزوں کے استعمال کا نتیجہ لازماً بدی اور بے ایمانی کے رنگ میں نہیں نکلتا.چنانچہ دیکھ لو.مسلمانوں میں سے بعض ایسے فرقے جو ان اشیاء کو مختلف تاویلات کے ذریعے جائز سمجھتے اور انہیں کھالیتے ہیں جیسے مالکی ان کا اثر ان کے ایمان پر نہیں پڑتااور اُن میں بے ایمانی اور بدی پیدا نہیں ہوتی.بلکہ گذشتہ دور میں تو ان میں اولیاء اللہ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں.لیکن خنزیر کا گوشت یا مُردار کھانے والا کوئی شخص ولی اللہ نظر نہیں آئےگا.پس حرمت کے بھی مدارج ہیں اور ان چاروں حرام چیزوں کے سوا باقی تمام ممنوعات ہیں جن کو عام اصطلاح میں حرام کہا جاتا ہے ورنہ قرآنی اصطلاح میں وہ حرام نہیں ہیں.دراصل ایک حرمت ایسی ہے.جو صرف لُغتاً حرمت کہلاتی ہے اس لحاظ سے ہر وہ چیزجس سے کسی دوسرے کو منع کر دیا جائے حرام کہلائےگی.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزیں ہیں.لیکن قرآنی اصطلاح میں صرف یہی چار چیزیں حرام ہیں.اس آیت میںمُردار کھانے سے اللہ تعالیٰ نے اس لئے روکا ہے کہ مردار کا خون بہت سی زہروں پر مشتمل ہوتا ہے اور مُردار کی نسبت اغلب گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ بیماری سے یا زہر سے یا زہریلے جانوروں کے کاٹے سے مرا ہو.یا بالکل بوڑھا ہو کر مرا ہو.اور یہ سب حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں جانور کا گوشت استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اگر گِر کر یا کسی اور صدمہ سے مرا ہو تب بھی قاعدہ ہے کہ سخت صدمہ کا اثر فوراً خون میں زہر پیدا کر دیتا ہے.پس درحقیقت کھانے کے قابل صرف وہی گوشت ہوتا ہے جو ذبح کئے ہوئے جانور کا ہو ورنہ اُس کا لازماً بد اثر ہو گا اور یہ چیز صرف خیالی نہیں بلکہ موجودہ طبّ نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ خواہ کوئی جانور عمر طبعی پا کر بوجہ بڈھا ہونے کے مرے یا کسی اونچے مقام سے گر کر ہلاک ہو یا کسی صدمہ سے جانبر نہ ہو سکے یا کسی بیماری کا شکار ہو اس کے خون میں کئی قسم کے خطرناک جراثیم اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں.چنانچہ میڈیکل جیورس پروڈنسMIDICAL JURISPRUDENCE جو ڈاکٹری کی ایک مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ مردہ کے گوشت میں بہت جلد
Page 123
کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن سے ایسے زہر پیدا ہوتے ہیں جنہیں AL-KALIDESA CADAVERICE یا PTOMAINESکہتے ہیں.یہ زہر سخت مہلک ہوتے ہیں اور ان کا اثر کچلا اور ایڑوپین کے مشابہ ہوتا ہے.اِسی طرح خون بھی مختلف قسم کی زہروں پر مشتمل ہوتا ہے اور صحت کے لئے سخت مضر چیز ہے.فزیالوجی والے لکھتے ہیں کہ خون انسانی بدن میں ایک ایسے گڑھے کی طرح ہوتا ہے جس میں بے حد مچھلیاں اور مینڈک اور کیڑے ہر وقت اپنی غذا بھی اُس سے لیتے ہوں اور اپنا فضلہ بھی اس میں پھینکتے ہوں.کیونکہ اس میں بے انتہا سیلز تیر رہے ہیں اور ہروقت اُسے خراب کر رہے ہیں.یہ خون کا ہی کام ہے کہ وہ ٹشوز سے مردہ مادہ کو ان آرگنز تک لے جاتا ہے جو اُسے خون سے صاف اور علیٰحدہ کرتے ہیں.پس خون مختلف قسم کے زہروں اور ردی مادوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور جسم کے اندر خدا تعالیٰ نے اُس کے صاف کرنے کے لئے کئی سامان بنائے ہوئے ہیں لیکن جب وہ جسم سے باہر آجائے تو اُس کے زہر اُس کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اور اس کا استعمال صحت کے لئے سخت مضر ہوتا ہے اور چند منٹ میں خراب ہو جاتا ہے بلکہ ہوا کے کیڑے مل کر بہت جلد نشوونما پا جاتے ہیں.چنانچہ وہ گوشت جس سے خون دھویا جائے دیر تک رہتا ہے بہ نسبت اس کے جسے خون لگا ہوا ہو.پس خون کا بد اثر بھی ظاہر ہے.خنزیر کے گوشت کا اثر بھی انسان کے جسم اور اُس کے اخلاق پر نہایت بُرا پڑتا ہے.جسم پر تو اُس کا اس طرح گندہ اثر پڑتا ہے کہ اس کے گند اور کیچڑ میں رہنے اور گندی ذہنیت کو پسند کرنے کے سبب سے اس کے گوشت سے کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں.چنانچہ مسٹر JONATHAN NICHOLSON اپنی کتاب SWINE FLESH میں لکھتے ہیں.'IT IS EXCEPTIONAL EVIDENCE AGAINST THE HATEFUL HOG WHEN WE SAY TAPE WORM, SCROFULA, CANCER AND ENEYSTER TRICHINA ARE UNKNOWN AMONG STRICT JEWS.THEY NEVER TOUCH THE HOG FLESH.' یعنی سؤر کے گوشت کے متعلق ایک غیر معمولی عجیب شہادت یہ ہے کہ کدو دانے اور سِل کا مادہ یہودیوں کے اندر اس لئے پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سؤر کا گوشت نہیں کھاتے.اگر ان کی یہ بات پورے طور پر تسلیم نہ بھی کی جائے تب بھی اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ سؤر خور قوموں میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں.سؤر کے گوشت سے ایک مہلک بیماری پیدا ہوتی ہے جسے’’TRICHINOSIS‘‘کہتے ہیں.اس میں
Page 124
پہلے ہیضہ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں پھر بخار ہوجاتا ہے پھر بدن میں درد شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں نمونیا ہو جاتا ہے.میڈیکل جیورس پروڈنس میں لکھا ہے کہ اس مرض کا کوئی علاج نہیں.اسی طرح سؤر کے گوشت سے آنتوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو کدّو دانہ کے مشابہ ہوتے ہیں اور سالہا سال تک رہتے ہیں.ڈاکٹر ایف بٹلر ایم.ڈی.ایف.آر.سی.پی اپنی کتاب ’’پریکٹس آف میڈیسن‘‘ میں لکھتے ہیں کہ سؤر میں یہ بیماری پاخانہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے لیکن ان ضرروں سے بھی بڑھ کر بلکہ اصل باعث اس کی حرمت کا وہ خرابیاں ہیں جو اخلاق میں پیدا ہوتی ہیں.صرف سؤرہی ایک ایسا جانور ہے جس میں نرکو نر پر پھاندنے کی عادت ہے پس وہ لوگ جو سؤر کا گوشت کھانے کے عادی ہیں ان میں بھی دیّوثی بڑھ جاتی ہے اور حیا کا مادہ کم ہو جاتا ہے.پھر اُس میں شجاعت بھی نہیں ہوتی بلکہ تہور کی عادت ہوتی ہے جس وقت اسے غصہ آجائے وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا بلکہ سیدھا حملہ کرتا ہے او راسی عادت کی وجہ سے شکاری اسے جلد مار لیتا ہے.جب شکار ی اُسے گولی مارتا ہے تو وہ غصہ میں سیدھا حملہ کرتا ہے اور اس طرح جلدی گِر جاتا ہے.اسی طرح جو قوم سؤر کا گوشت کھانے والی ہوگی اس میں بھی شجاعت نہیں پائی جائے گی بلکہ تہوّر پایا جائے گا.بانی سلسلہ احمدیہ اپنی مشہور تصنیف’’اسلامی اصول کی فلاسفی‘‘ میں خنزیر کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:.’’ایک نکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے قابل ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ خنزیر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتداء سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ خنزیر کا لفظ خنز اور اَر سے مرکب ہے جس کے یہ معنے ہیں کہ میں اس کو فاسد اور خراب دیکھتا ہوں.خنز کے معنے بہت فاسد.اَرٰ کے معنے دیکھتا ہوں پس اس جانور کا نام جو ابتداء سے خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہے وہی اس کی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور کہتے ہیں یہ لفظ بھی سوء اور اَر سے مرکب ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ میں اس کو بہت بُرا دیکھتا ہوں.…… اور یہ معنے جو اس لفظ کے ہیں یعنی بہت فاسد اس کی تشریح کی حاجت نہیں.اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور د ّیوث ہے.اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانونِ قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اثر بدن اور روح پر پلید ہی ہو.کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذائوں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے.پس اس میں کیا شک ہے
Page 125
کہ ایسے بد کااثر بھی بد ہی پڑے گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور د ّیوثی کو بڑھاتا ہے‘‘.چوتھی چیز جسے حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے جوشرک کے طور پر ذبح کی جائے اور اس کے قربان کرنے کا باعث خدا تعالیٰ کے سوا اور ہستیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی خواہش ہو.چونکہ اس میں خدائے وحد ہ ٗلا شریک کی ہتک کی جاتی ہے اور اس کی صفات دوسری ہستیوں کو دی جاتی ہیں اس لئے اس کو استعمال کرنا انسان کو بے غیرت بناتا ہے بلکہ درحقیقت ایسے جانور کو کھانا دلی ناپاکی اور بے غیرتی کی علامت ہے.پس اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے.یہ حرمت اس کے طبعی نقصانات سے نہیں بلکہ دینی نقصانات کی وجہ سے ہے کیونکہ جو شخص کسی ایسے جانور کا گوشت کھاتا ہے جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ اس بات کا ثبوت بہم پہنچاتا ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ کی توحید سے کوئی محبت نہیں.وہ بظاہر خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے باطن میں اس نے اور بھی کئی بُت چُھپا رکھے ہیں جن کی وہ پرستش کرتا ہے.پس اس کا کھانا اس کے دل کو ناپاک کرتا اور اُسے مشرکوں کا ہمرنگ بنا دیتا ہے.عیسائی لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے تورات کی نقل کرتے ہوئے ان اشیاء کو حرام قرار دیا ہے کسی حکمت کی وجہ سے ان کو حرام قرار نہیں دیا.مگر ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے.کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تورات نے حرام کیا ہے مگر قرآن نے حرام نہیں کیا مثلاً اونٹ کو تورات میں حرام قرار دیا گیا ہے (احبار باب۱۱ آیت۴) لیکن اسلام میں اس کا کھانا جائز ہے اگر کہو کہ عربوں کی خاطر اُسے حرام نہیں کیا گیا.تو میں کہتا ہوں کہ خرگوش کو بھی تورات میں حرام کیا گیا ہے (احبار باب۱۱ آیت۶) لیکن اسلام میں اس کا کھانا بھی جائز ہے.اگر اونٹ عربوں کی خاطر حلال کیا گیا تھا تو خرگوش کو حلال قرار دینے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر اگر یہ احکام تورات کی ہی نقل ہوتے تو چاہیے تھا کہ تورات کے تمام احکام کو نقل کر لیا جاتا مگر قرآن کریم نے اس کے بہت سے احکام کو چھوڑ دیا ہے.مثلاً تورات نے مُردار کھانے والے کے لئے یہ سزا مقرر کی ہے کہ وہ ناپاک ہو جائے گااور کپڑے دھونے کے بعد بھی شام تک ناپاک رہے گا (احبار باب۱۱ آیت۳۹،۴۰) لیکن قرآن کریم نے اس بے معنی بات کو چھوڑ دیاہے.پس یہ کہنا کہ قرآن نے تورات کی نقل کی ہے واقعات کے لحاظ سے بالکل غلط بات ہے.دوسرا جواب یہ ہے کہ تورات نے تو حرمت کی کوئی وجہ بیان نہیں کی لیکن قرآن کریم حرمت کی وجہ بھی بتاتا ہے.چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَّاۤ اَجِدُ فِيْ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ١ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ
Page 126
رَّحِيْمٌ(الانعام :۱۴۶) یعنی ُتو ان سے کہہ دے کہ جو کچھ میری طرف نازل کیا گیا ہے میں تو اس میں اُس شخص پر جو کسی چیز کو کھانا چاہے سوائے مردار یا بہتے ہوئے خون یا سؤر کے گوشت کے کوئی چیز حرام نہیں پاتا.اس لئے کہ ان میں سے ہر ایک چیز نجس ہے یا میں فسق کو حرام پاتا ہوں.یعنی اس چیز کو جس پر خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو.لیکن جو شخص اس کے کھانے پر مجبور ہو جائے بغیر اس کے کہ وہ شریعت کا مقابلہ کرنے والا ہو یا حد سے نکلنے والا ہو یعنی وہ جان بوجھ کر ایسے موقع پر نہ گیا ہو یا کھاتے وقت ضرورت سے زیادہ نہ کھائے تو وہ یاد رکھے کہ تیرا ربّ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے یعنی ایسا شخص اگر ان کھانوں کو کھالے تو اللہ تعالیٰ اُس کو اُن کے بد اثرات سے بچا لے گا.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مردہ اور بہا ہوا خون اور سؤر کا گوشت حرام کرنے کی وجہ ان کا تکلیف دہ ہونا ہے کیونکہ رجس کے معنے گند اور عذاب کے ہوتے ہیں.پس مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں گندی ہیں اور انسان کے لئے رُوحانی اور جسمانی طور پر موجب دکھ ہیں.اس کے علاوہ سورۃ مائدہ آیت ۴ اور سورۃ نحل آیت ۱۱۶ میں بھی حلال اور حرام اشیاء کا ذکر ہے اور سب میں یہی چیزیںبیان کی گئی ہیں.سوائے سورۃ مائدہ کے کہ وہاں مَیْتَۃٌ کی تشریح کر کے بتایا ہے کہ اس میں گلا گھونٹا ہوا یا لاٹھی سے مارا ہوا بھی شامل ہےا سی طرح بلندی سے گرکر مرنے والا جانور یا سینگ لگنے سے مرا ہوا جانور یا وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو وہ بھی مردار کے حکم میں شامل ہے.اُھِلَّ بِہٖ لِغَیْرِ اللّٰہِ کو اس لئے علیحدہ بیان کیا ہے کہ اگرچہ اس سے ظاہری طور پر کوئی نقصان معلوم نہیں ہوتا مگر اس کے استعمال کرنے سے روحانی رنگ میں یہ بُرا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر اباحت اور بے دینی پیدا ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے.پس بائیبل نے تو بغیر کوئی حکمت واضح کرنے کے بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا.مگر قرآن کریم نے حرام کرنے کی وجہ بھی بتائی ہے پس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حلّت و حرمت کے مسائل تورات سے نقل کر لئے گئے ہیں.فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ میں پہلی شرط تو یہ رکھی کہ یہ استثناء صرف اس شخص کے لئے ہے جو مضطر ہو جائے اور اضطرار کے معنے کسی شخص کو کسی ایسے کام پر مجبور کر دینے کے ہیں جو اس کے لئے باعثِ ضر ر ہو یا جسے وہ ناپسند کرتا ہو.اور یہ مجبوری دو قسم کی ہوتی ہے ایک بیرونی تہدید و تخویف اور ایک اندرونی جیسے ہیجانِ جذبات اور مطالبات نیچر وغیرہ (مفردات راغب) دوسری شرط یہ رکھی کہ وہ باغی یعنی سرکش اور قانون شکن نہ ہو.تیسری شرط یہ رکھی کہ وہ عادی یعنی حد سے گذرنے والا نہ ہو.باغی کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی اپنے کسی عیسائی دوست کے گھر میں بیٹھا ہوا ہو اور
Page 127
وہ بے تکلفی سے گھر والوں سے کہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لئے دو اور وہ سؤر کا گوشت سامنے رکھ دیں تو وہ اُسے بے تکلّف کھانے لگ جائے یہ بغاوت اور نافرمانی ہو گی.سؤر کا گوشت کھانا صر ف اُس وقت جائز ہو گا جب وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو اور اُسے کھانے کے لئے سؤر کے گوشت کے سوا اور کوئی چیز کھانے کی میسر نہ آرہی ہو.کیونکہ اس وقت اس کے استعمال میں نقصان کم اور عدمِ استعمال میں نقصان زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وَلَا عَادٍ فرما کر بتا دیا کہ مضطر کو بھی ُکلّی طور پر اجازت نہیں دی گئی کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے بلکہ صرف اتنا کھانے کی اجازت دی گئی ہے جس سے اس کی زندگی قائم رہ سکے.اگر وہ ان حدود کا خیال رکھے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہو گا.لیکن اگر وہ اس خیال سے کہ آج تو پہلی مرتبہ سؤر کا گوشت کھانے کا موقعہ ملا ہے خوب سیر ہو کر کھا لے تو یہ ناجائز ہو گا.بہر حال اضطرار تاویلی نہیں بلکہ حقیقی ہونا چاہیے تب ان چیزوں کا استعمال اس کے لئے جائز ہو گا.آخر میں فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسی مجبوری کی حالت میں کھانے والے پر کوئی گناہ نہیں تو بخشنے کے کیا معنے ہوئے اور اگر ایسی حالت میں کھانا بھی گناہ ہے تو پھر فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ کا کیامطلب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ لگتا ہے کہ انسان سے جو کمزوریاں سر زد ہوتی ہیںوہ بھی اس کی کسی مخفی شامتِ اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں.چونکہ اس جگہ ایسے لوگوں کا ذکرکیا جا رہا تھا جنہیں مجبوری کی حالت میں لحمِ خنزیر وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارا اس حالت کو پہنچنا بتاتا ہے کہ تم تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں تھے ورنہ خدا تعالیٰ تمہیں اس حالت سے بچا لیتا اور تمہارے رزق کے لئے غیب سے کوئی اور صورت پیدا فرما دیتا.آخر آج تک اُمتِ محمدیہ میں لاکھوں اولیاء اللہ گذرے ہیں کیا کسی ادنیٰ سے ادنیٰ ولی کے متعلق بھی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اُس پر ایسا فاقہ آیا کہ وہ مردار یا سؤر کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گیا.اگر نہیںتو پھر ایسے شخص کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اُس سے اپنی پہلی زندگی میں کوئی نہ کوئی قصور ایسا ضرور سرزد ہواہے جس کی پاداش میں اُسے یہ دن دیکھنا پڑا کہ وہ مومن کہلاتے ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے ہوتے ہوئے سؤر کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گیا.بے شک ایسی حالت میں اُس کا بقدر ضرورت چند لقمے لے لینا اور موت سے اپنے آپ کو بچا لینا جائز ہے لیکن چونکہ اس کی یہ حالت کسی مخفی شامت اعمال کا نتیجہ ہو گی اس لئے اُسے چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنی گذشتہ کمزوریوں پر ندامت کے آنسو بہائے.خدا تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار سے کام لے اور دُعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کمزوریوں کو معاف فرمائے اور ان پر پردہ ڈالے اور اُسے
Page 128
اپنی مغفرت کے دامن میں لے لے.اگر وہ سچے دل سے ایسا کرےگا تو وہ اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا اور آئندہ اس قسم کے حالات میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو جائے گا.ایک صحابیؓ کا واقعہ ہے انہیں جنگ میں پکڑ کر اور قید کر کے قیصر کے پاس بھیجا گیا.اس نے چاہا کہ انہیں قتل کر دے مگراس کے مصاحبوں نے کہا کہ قتل نہیں کرنا چاہیے.کیونکہ مسلمان بھی ہمارے قیدیوں کو قتل نہیں کرتے اور اگر عمرؓکو پتہ لگ گیا کہ اُن کے ایک آدمی کو قتل کیا گیا ہے تو وہ اس کا سختی سے انتقام لیں گے.قیصر نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ اسے ایسی سزا دوں جو دوسروں کے لئے باعثِ عبرت ہو.اس پر انہوں نے کہا.اسے سؤر کا گوشت کھلانا چاہیے.چنانچہ انہوں نے اس صحابیؓ کو چند دن بھوکا رکھا اور پھر سؤر کا گوشت کھانے کو دیا اس نے کھانے سے سختی سے انکار کر دیا وہ اُسے کھانے پر مجبور کر رہے تھے کہ قیصر کے سر میں شدید درد شروع ہوگئی جس کا اُن سے کوئی علاج نہ ہو سکا.اس کے مصاحبوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے یہ اس شخص کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہے.آخر یہ قرار پایا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو دُعا کے لئے لکھا جائے.اور چونکہ ایسی صورت میں ان کے لئے یہ مناسب نہ تھا کہ ایک مسلمان پر وہ ایسی سختی کریں ورنہ دعا مشکل تھی.اس لئے وہ مجبور ہو کر اُسے کھانا دینے لگ گئے پس جو لوگ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں خدا تعالیٰ ان پر ایسا موقعہ ہی نہیں لاتا کہ انہیں حرام چیز کھانی پڑے.خدا تعالیٰ خود ان کے لئے ہر قسم کی خیرو برکت کے سامان مہیا کر دیتا ہے.اس کادوسرا جواب یہ ہے کہ اگر کسی موقعہ پر انتہائی مجبوری کی وجہ سے مردار یا سؤر کا گوشت استعمال کر لیا جائے تو جن زہریلے اثرات کی وجہ سے شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ بہر حال ایک مومن کے لئے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں.ان نتائج کا تدارک اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ انسان غفور اور رحیم خدا کا دامن مضبوطی سے پکڑلے اور اُسے کہے کہ اے خدا! میں نے تو تیری اجازت سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لئے اس زہریلے کھانے کو کھالیا ہے لیکن اب تو ہی فضل فرما اور ان مہلک اثرات سے میری روح اور جسم کو بچا جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں.اسی حکمت کے باعث آخر میں اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ کہاگیا ہے.تاکہ انسان مطمئن نہ ہوجائے بلکہ بعد میں بھی وہ اس کی تلافی کی کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے اُس کی حفاظت طلب کرتا رہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غالباً شریعت کی اسی رخصت کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کسی حاملہ عورت کی حالت ایسی ہو جائے کہ مرد ڈاکٹر کی مدد کے بغیر اُس کا بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو اور وہ ڈاکٹر کی مدد نہ لے اور اُسی حال میں مر جائے تو اس عورت کی موت خود کشی سمجھی جائے گی اسی طرح اگرانسان کی ایسی حالت ہو جائے کہ
Page 129
وہ بھوک کے مارے مرنے لگے اور وہ سؤر یا مُردار کا گوشت کسی قدر کھالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں.اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ جو لوگ اس (تعلیم )کو جو اللہ نے (الٰہی )کتاب (میں )نازل کی ہے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا١ۙ اُولٰٓىِٕكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا قیمت لیتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں صرف آگ ڈالتے ہیں النَّارَ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ١ۖۚ وَ اور قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک قراردے گا اور لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۰۰۱۷۵ ان کے لئے درد ناک عذاب (مقدر )ہے.تفسیر.فرماتا ہے.وہ لوگ جو اس عظیم الشان تعلیم کو چھپاتے ہیں جسے خدا نے لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے اور اس کے بدلہ میں دنیوی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ انڈیلتے ہیں.یہ آیت حلت و حرمت کے مسائل کے بیان کرنے کے معاً بعد لا کر اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس طرح مُردار اور خون اور سؤر کا گوشت تم پر حرام ہے اور جس طرح غیر اللہ کے نام پرذبح کیا ہوا جانور کھانا تمہارے لئے گناہ ہے اسی طرح یاد رکھو کہ خدا اور اس کے رسول کے احکام کو چھپانا اور دنیوی مال وجاہ یا عہدوں کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے دینا اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ دینا بھی مُردار اور سؤر کا گوشت کھانے سے کم نہیں.جس طرح وہ حرام خور ی ہے اسی طرح یہ بھی حرام خوری ہے کہ انسان دین سے واقف ہوتے ہوئے کلمہ حق کہنے سے احتراز کرے.اور ڈرے کہ اگر میں نے اپنے عقیدہ کو نہ چھپایا یا خدا اور اس کے رسول کے احکام کا بر ملا اظہار کر دیا تو میری ملازمت جاتی رہے گی یا میری تجارت ماری جائےگی یا میرے دوستوں کے حلقہ میں میری عزت کم ہو جائےگی.فرماتا ہے جو لوگ صحیح علم رکھنے کے بعد بھی منافقت سے کام لیتے ہیں اور
Page 130
دنیوی مفاد کو دینی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنے پیٹوں میں انگارے ڈال رہے ہیں.مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ.اس آیت میں بُطُوْن کا لفظ تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور فِیْ بُطُوْنِھِمْ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے بطون کے اندر آگ کا عذاب پیدا کیا جائے گا.یعنی انہیں اندرونی عذاب دیا جائےگا جو بیرونی عذاب سے زیادہ سخت ہوتا ہے.اسی مفہوم کو ایک شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے کہ ؎ دُخُوْلُ النَّارِ لِلْمَھْجُوْرِ خَیْرٌ مِنَ الْھِجْرِ الَّذِیْ ھُوَ یَتَّقِیْہِ لِاَنَّ دُخُوْ لَہٗ فِی النَّارِ اَدْنٰی عَذَابًا مِنْ دُخُوْلِ النَّارِ فِیْہِ یعنی ایک مہجور انسان جو اپنے محبوب کے فراق میں نالہ و فریاد کر رہا ہو اس کا آگ میں داخل ہو جانا اس جدائی کی آگ سے زیادہ آسان ہوتا ہے جس سے وہ بچنا چاہتا ہے.کیونکہ اس کا آگ کے اندر داخل ہونا اس سے کم تکلیف دہ ہے کہ آگ اس کے اندر داخل ہو جائے اور وہ اس کے رگ و ریشہ کو جلا کر راکھ کر دے.اسی محاورہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آگ میں داخل کئے جائیں گے بلکہ فرمایا کہ وہ آگ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں.یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لئے ایک اندرونی جہنم تیار کر رہے ہیں.گویا اس آیت میں سبب کی جگہ مسبّب استعمال ہوا ہے.وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کلام تک نہیں کرے گا.یہ ایک عظیم الشان نکتہ تھا جسے افسوس کہ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں نے فراموش کر دیا.فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اُن سے نہیں بولےگا حالانکہ قیامت کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کافروں سے بھی کلام کرے گا.جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے وَ يَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَقُوْلُ مَا ذَاۤ اَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِيْنَ(القصص: ۶۶) یعنی اس دن خدا تعالیٰ کفار کو پکارے گا اور کہےگا تم نے میرے رسولوں کے پیغام کا کیا جواب دیا تھا؟ پس قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کا کفار سے بھی کلام کرنا ثابت ہے تو بعض لوگوں سے اس کا منہ پھیر لینا اور ان سے کلام تک نہ کرنا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے شدید ناراض ہو گا.اور وہ نہیں چاہے گا کہ ان سے زجر کے رنگ میں بھی کلام کرے.گویا اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا اُس کی ناراضگی کا نتیجہ ہوتا ہے.مگر اس زمانہ کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کلام نہ کرنا نعوذباللہ ایک بڑی نعمت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امتِ محمدیہ کو حاصل ہوئی حالانکہ خیرِ اُمت کی علامت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا دروازہ ان پر زیادہ سے زیادہ کھولتا اور پہلی قوموں سے بھی زیادہ
Page 131
انہیں شرفِ مکالمہ و مخاطبہ عطا فرماتا.مگر انہوں نے زحمت کو رحمت سمجھ لیا اور خدا تعالیٰ سے دُوری کو ایک انعام سمجھ کر اُسے حرز جان بنا لیا.اس آیت کا ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کا کلام نہیں کرےگا.اور یہ عام محاورہ ہے.ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ میں تم سے بات نہیں کروںگا.اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں تم سے دوستانہ کلام نہیں کروںگا پس اس کے ایک معنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روز ان سے دوستانہ کلام نہیں کرےگا.بلکہ اس کا کلام ایسا ہی ہوگا جیسے ایک جج کسی مجرم کو سزا کاحکم سُناتے وقت کلام کرتا ہے.مگر بہر حال خواہ کوئی معنے لئے جائیں خدا تعالیٰ کا ترک گفتگو اس کی ناراضگی کی نشانی ہے.مگر مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذباللہ خدا تعالیٰ کا اُمت محمدیہ پر یہ انعام نازل ہوا کہ اس نے ان سے کلام کرنا ترک کر دیا اور وحی اور الہام کے سلسلہ کو منقطع کر دیا.پھر فرمایا وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ.چونکہ اسلام کی رو سے کفار کو دوزخ میں ڈالنے کی غرض ہی یہی ہے کہ ان کا تزکیہ ہو اس لئے وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ کے یہ معنے نہیں کہ وہ انہیں پاک نہیں کرےگا.بلکہ یہ معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک قرار نہیں دے گا.ترتیب وربط.ان آیات میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ساتھ ہی یہود کو بھی مدِّنظر رکھا گیا ہے چنانچہ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَمیں ان کے اس اعتراض کو دُور کیا گیا ہے کہ یہ نبی ان چیزوں کو کیوں حلال کرتا ہے جو شریعت موسویہ میں حرام تھیں؟اگر یہ ان پیشگوئیوں کا مصداق ہے تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اعتراض قلّتِ تدبّر کا نتیجہ ہے.جو احکام کسی خاص وقت کے مناسب حال تھے ان کو دوام کا رنگ نہیں دیا جا سکتا تھا اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے یہود کے ہاں اونٹ حرام تھا.مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت حلال تھا.پس جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے قبل بعض چیزیں حلال تھیں اور کئی انبیاء تک ان کو استعمال کرتے رہے مگر بعد میں ان کو حرام کر دیا گیا.اسی طرح موسوی شریعت کے بعد بھی خدا تعالیٰ اختیار رکھتا تھا کہ وہ بعض حرام سمجھی جانے والی چیزوں کو حلال کر دیتا.پس اس پر اعتراض کرنا نادانی کی علامت ہے.
Page 132
اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَ الْعَذَابَ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اور مغفرت چھوڑ کر عذاب اختیار کر لیا ہے.بِالْمَغْفِرَةِ١ۚ فَمَاۤ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ۰۰۱۷۶ پس آگ (کے عذاب) پر ان کی برداشت تعجب انگیز ہے.حل لغات.اِشْتَرَوْا اِشْتَرٰی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِشْتَرَاہُ کے معنے ہیں مَلَکَہٗ بِالْبَیْعِ کسی چیز کا خرید کے ذریعہ سے مالک ہو گیا.بَاعَہٗ نیز اس کے معنے ہیں اس کو بیچا یعنی یہ لفظ اضداد میں سے ہے.اور متضاد معنے دیتا ہے خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی.وَکُلُّ مَنْ تَرَکَ شَیْئًا وَ تَمَسَّکَ بِغَیْرِہٖ فَقَدِ اِشْتَرَاہُ.ہر وہ شخص جو ایک چیز کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کو اس کی بجائے اختیار کر لے اس پر اِشْتَرٰی کا لفظ بولیں گے.گویا اس نے ایک چیز دے کر دوسری لے لی.(اقرب) عام طور پر شَرَا کسی چیز کو خرید نے اور لفظ بَیْع کسی چیز کے بیچنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.لیکن جب سامان کو سامان کے بدلہ میںتبادلہ کیا جائے تو دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیا کرتے ہیں.لیکن لفظ شَرَا اور اِشْتَرٰی کا استعمال اس طرح بھی جائز ہے کہ جو شخص ایک چیز کو ترک کر دے اور دوسری کو اختیار کرے تو اس کی نسبت کہیں گے کہ شَرَا ہُ یا اِشْتَرَاہُ.(مفردات) اَلضَّلٰـلَۃُ ضَلَّ یَضِلُّ کے معنے ہیں ضِدُّ اِھْتَدٰی یعنی ہدایت کے خلاف حالت پر ہو گیا اور دین اور حق نہ پایا.ضَلَّ عَنْہُ یَضِلُّ : لَمْ یَھْتَدِ اِلَیْہِ اس طرف راہ نہ پائی.ضَلَّ یَضَلُّ (ضاد کی زبر سے) فُـلَانٌ الطَّرِیْقَ وَعَنِ الطَّرِیْقِ لَمْ یَھْتَدِ اِلَیْہِ راستہ نہ پایا.جب دار یا منزل یا ہر اپنی جگہ پر قائم رہنے والی چیز کا اس کے بعدذکر ہو تو اس کے یہی معنے ہوتے ہیں.ضَلَّ الرَّجُلُ فِی الدِّیْنِ ضَلَا لًا وَضَلَالَۃً : ضِدُّ اِھْتَدٰی.اس شخص نے دین کے معاملہ میں درست راہ نہ پائی.ضَلَّ فُـلَانٌ الْفَرَسَ فلاں شخص نے اپنا گھوڑا گم کر دیا.ضَلَّ عَنِّیْ کَذَا : ضَاعَ مجھ سے فلاں چیز ضائع ہو گئی.ضَلَّ الْمَاءُ فِی اللَّبَنِ.خَفِیَ وَغَابَ پانی دودھ میں مل گیا اور غائب ہو گیا.ضَلَّ فُـلَانٌ فُـلَانًا: نَسِیَہٗ اس شخص کو بھول گیا.ضَلَّ النَّاسِیْ : غَابَ عَنْہُ حِفْظُ الشَّیْءِ.بھول گیا.اس کے ذہن سے بات نکل گئی.ضَلَّ سَعْیُہٗ : عَمِلَ عَمَلًا لَمْ یَعُدْ عَلَیْہِ نَفْعُہٗ ایسا کام کیا کہ جس کا
Page 133
اسے کوئی نفع نہ ہوا.(اقرب) ھُدٰی اَلرَّشَادُ.سیدھے راستہ پر ہونا.اَلْبَیَانُ بیان کرنا.اَلدَّ لَالَۃُ.کسی امر کی طرف رہبری کرنا (اقرب) اَلْھَدَایَۃُ الدَّلَالَۃُ بِلُطْفٍ یعنی ہدایت (جو ھُدًی کاہم معنی دوسرا مصدر ہے) کے معنی محبت اور نرمی سے کسی امر کی طرف رہبری کرنے کے ہیں.(مفردات) یہ مصدر ہے اور فاعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے.یعنی لوگوں کو ہدایت دینے والا.امام راغب کے نزدیک ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں مندرجہ ذیل چار معنوں میں آتا ہے (۱) ہر عقل یا سمجھ یا ضروری جزوی ادراک کی طاقت رکھنے والی شے (جیسے حیوانات وغیرہ کہ اِدراکِ کامل ان کو حاصل نہیں ہوتا صرف جزوی یا سطحی اِدراک ایسے ضروری امو رکا جو ان کی حیات اور محدود عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے) کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام کا طریق بتانا.اس کی مثال قرآن کریم میں یہ ہے رَبُّنَا الَّذِيْۤ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى (طہٰ:۵۱) یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی عقل یا سمجھ یا اس کے ضروری تقاضوں کے مطابق اسے رہنمائی کی (میرے نزدیک اس جگہ ھدی کے معنے یہ ہیں کہ ہر شے میں مناسب قوتیں پیدا کر کے پھر انہیں کام پر لگا دیا کیونکہ صرف قوتوں کا موجود ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ انہیں ابتدائی حرکت دے کر کام پر لگانا ان کی حیات کے شروع کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گو پیدائش سے پہلے آلاتِ تنفّس کامل طور پر موجود ہوتے ہیں مگر باہر نکلنے کے بعد جب تنفّس کے آلات کو ہوا لگنے یا پانی کا چھینٹا دینے سے ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے بچہ کی عملی زندگی در حقیقت اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جس طرح ایک گھڑی کے اندر سب ہی پُرزے موجود ہوتے ہیں مگر جب تک اُسے ُکنجی دے کر حرکت نہ دی جائے پُرزے کام کرنا شروع نہیں کرتے غرض حیات کو شروع کرنے سے پہلے ایک ابتدائی دھکے کی ہر شے کو ضرورت ہوتی ہے اور ہدایت سے مراد وہی حرکت اُولیٰ ہے اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو مناسب قویٰ کے ساتھ پیدا کیا ہے او رپھر حرکت ِ اُولیٰ دے کر اسے مفوضہ کام پر لگا دیا ہے) علّامہ راغب کے نزدیک ہدایت کے دوسرے معنے اس ارشاد کے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے بندوں تک پہنچاتا ہے اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا (السجدۃ:۲۵) ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے امام مقرر کئے جو ہمارے الہام سے لوگوں کو ہماری طرف بلاتے تھے.ہدایت کے تیسرے معنے ان کے نزدیک اس توفیق کے ہیں جو ہدایت پانے والوں کو ملتی ہے یعنی ہدایت ملنے کے بعد جو عمل کی توفیق یا فکر
Page 134
کی بلندی پیدا ہوتی ہے یا مزید ہدایت کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہدایت کہلاتی ہے اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَ الَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى (محمد:۱۸) جو لوگ ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے (یعنی عمل کی توفیق اور ہدایت کے سلسلہ میں مزید فکر کرکے اور علوم حاصل کرنے کا موقعہ عطا کرتا ہے).چوتھے معنی ہدایت کے انجام بخیر کے اور جنت کو پالینے کے ہیں اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہےسَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ(محمد:۶) اللہ تعالیٰ ان کا ا نجام بخیر کر کے انہیں جنت تک پہنچا دے گا اور ان کے حالات کو درست کر دے گا اور قرآن کریم میں جہاں یہ آتا ہےيَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا (الانبیاء:۷۴)وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے تھے یا لِکُلِّ قَوْمٍ ھَادٍ (الرعد:۸) ہر قوم میں ہادی آیا ہے اس جگہ ہدایت سے مراد لوگو ںکو ہدایت کی دعوت دینے کے ہیں اور ایسی آیات جیسے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ (القصص:۵۷) اور ایسی آیات جن میں یہ ذکر ہے کہ کافروں اور ظالموں کو ہدایت نہیں مل سکتی.اس سے مراد تیسری اور چوتھی قسم کی ہدایتیں ہیں یعنی ہدایت پاجانے کے بعد توفیق ِ عمل کا ملنا یا نورِ ایمان کا عطا ہونا یا جنت میں داخلہ کی نعمت کا حصول.پس ان آیات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کفار کو مذکور ہ بالا انعامات نہیں مل سکتے.(مفردات راغب) تفسیر.فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی اور مغفرت کی بجائے عذاب کو اختیار کر لیا ہے.پس آگ کے عذاب پر ان کی برداشت تعجب انگیز ہے.یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کوئی جبر نہیں کیا بلکہ اُسے نیکی اور بدی کے اختیار کرنے پر کامل مقدرت بخشی ہے.اور پھر انبیاء کے ذریعہ اس نے بنی نوع انسان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہدایت کیاہے اور ضلالت کیا ہے؟ اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ عقل اور اس کے کلام سے فائدہ اٹھا کر ہدایت کی راہ اختیار کرے یا شیطان کے پیچھے چل کر ضلالت کو اختیار کر لے.اگر وہ ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دیتا ہے تو اس کے نتائج بھی طبعی طور پر اسے عذاب کی صورت میں برداشت کرنے پڑتے ہیں.اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اس جسارت اور نابینائی پر تعجب کا اظہار کرتا ہے.اور فرماتا ہے فَمَاۤ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ.جب انہوں نے مغفرت پر عذاب کو ترجیح دی ہے تو ان کی عذاب کو برداشت کر لینے کی جرأت بڑی تعجب انگیز ہے.اس آیت کے متعلق یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خدا تعالیٰ بھی تعجب کا اظہار کیا کرتا ہے؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کلام میں حقیقی تعجب مراد نہیں ہوتا بلکہ اس سے یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کیسی بے وقوفی کر رہے ہیں.
Page 135
کیا یہ بھی کوئی ایسی چیز تھی جسے اپنے اوپر وارد کر کے وہ صبر کرتے.پس فَمَاۤ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ واقعہ میں بڑے صبر کرنے والے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کے صبر کی تعریف کر رہا ہے یا ان کے صبر پر تعجب کا اظہار کر رہا ہے بلکہ یہ تعریض ہے اور اس سے لوگوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان بیوقوفوں کی موجودہ حالت بتاتی ہے کہ یہ لوگ عذاب پر بہت ہی صبر کرنےوالے ہیں.نہ یہ کہ عذاب پر وہ واقعہ میں صبر کریںگے کیونکہ معمولی عذاب بھی انسان کی قوتِ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے.لیکن اس کے علاوہ اگر مَا کو استفہامیہ قرار دیا جائے تو اس کے معنے یہ ہوںگے کہ کس چیز نے انہیں آگ پر صبر کرنےوالا بنا دیا؟ اور اگر مَا کو نافیہ قرار دیا جائے تو پھر اس آیت کے یہ معنے ہوںگے کہمَاۤ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ.اللہ تعالیٰ انہیں آگ پر صبر نہ دے.یعنی خوب سزا دے اور وہ سزا ان کو اچھی طرح محسوس ہو.ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ١ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ یہ( عذاب) اس سبب سے ہوگا کہ اللہ نے اس کتاب کو( مشتمل) برحق اتارا ہے اور جن لوگوں نے اس کتاب کے اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍؒ۰۰۱۷۷ بارہ میں اختلاف کیاہے وہ یقیناً پرلے درجہ کی عداوت میں (مبتلا)ہیں.حل لغات.شِقَاقٌ شَاقَّ کا مصدر ہے اور شَاقَّہٗ کے معنے ہیں خَالَفَہٗ وَعَادَاہُ.وَحَقِیْقَتُہٗ اَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا فِیْ شِقٍّ غَیْرِ شِقِّ صَاحِبِہٖ یعنی اس نے اس کی مخالفت اور دشمنی کی اور اس کے حقیقی معنے یہ ہیں کہ دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی مخالف جانب سے آیا.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے یہ عذاب انہیں اس وجہ سے ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بھاری احسانات سے کام لیتے ہوئے انہیں ایک ایسا قانون بخشا تھا جس کا ایک ایک حرف صداقت پر مشتمل ہے.مگر ان لوگوں نے انتہا درجہ کی عداوت اور دشمنی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسے ٹھکرا دیا.اور خدائی پیغام کے منکر بن گئے.شِقَاقٍ بَعِیْدٍ سے ایسی عداوت مراد ہے جو اپنی شدت میں انتہا درجہ تک پہنچی ہوئی ہو اور جس کا سلسلہ ایک طویل مدت تک بھی منقطع نہ ہو.
Page 136
لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ تمہارا مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةِ وَ لیکن کامل نیک وہ شخص ہے جو اللہ ، روز آخرت، ملائکہ،(الٰہی )کتاب الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ١ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ اور سب نبیوں پر ایمان لایا.اور اس (یعنی اللہ) کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروںاور الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ١ۙ وَ السَّآىِٕلِيْنَ۠ وَ فِي یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کو اور سوالیوں کو نیز غلاموں (کی آزادی ) کے لئے الرِّقَابِ١ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ١ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ (اپنا)مال دیا.اور نماز کو قائم رکھااور زکوۃ کو ادا کیا اور اپنے عہدوں کو جب بھی کو ئی عہد کر لیں بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا١ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ پورا کرنے والے اور (خاص کر ) تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے وقت برداشت سے کام لینے والے الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ١ؕ اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا١ؕ وَ اُولٰٓىِٕكَ (کامل نیک ہیں).یہی لوگ ہیں جو (اپنے قول کے)سچے نکلے.هُمُ الْمُتَّقُوْنَ۰۰۱۷۸ اور یہی لوگ کامل متقی ہیں.حل لغات.اَلْبِرُّ اَلصِّلَۃُ وَ الطَّاعَۃُ وَالصِّدْقُ.بِرّ کے معنے صلہ رحمی، اطاعت اور سچائی کے ہیں.(اقرب)
Page 137
مفرداتِ امام راغب میں لکھا ہے اَلْبِرُّ: اَلتَّوَسُّعُ فِیْ فِعْلِ الْخَیْرِ.پھر لکھاہے بَرَّ الْعَبْدُ رَبَّہٗ اَیْ تَوَسَّعَ فِیْ طَاعَتِہٖ فَمِنَ اللّٰہِ تَعَالیٰ اَلثَّوَابُ وَفِی الْعَبْدِ اَلطَّاعَۃُ.یعنی بِرّ کے معنے ہیں نیکی میں وسعت اختیار کرنا.چنانچہ بَرَّ الْعَبْدُ رَبَّہُ کے معنے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وسعت اختیار کی.برّ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد ثواب دینا ہے اوراگر بندے کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد اطاعت کرنا ہے.اَلْبَاسَآءُ کے معنے ہیں اَلشِّدَّۃُ شدت (۲) اِسْمٌ لِلْحَرْبِ جنگ (۳) اَلْمُشَقَّۃُ وَالضَّرْبُ مشقت اور مار.(اقرب) اَلضَّرَّآءُ کے معنے ہیں(۱) اَلزَّمَانَۃُ قحط(۲) اَلشِّدَّۃُ سختی و مصیبت (۳) اَلنَّقْصُ فِی الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ.مال اور افرادمیں کمی (۴) نَقِیْضُ السَّرَّآءِ یہ سَرَّاء یعنی فراخی کا اُلٹ ہے.(اقرب) اَلْبَاْسُ کے معنے ہیں (ا) اَلْفَقْرُ مالی مشکلات.(۲) اَلْعَذَابُ عذاب (۳) اَلشِّدَّۃُ فِی الْحَرْبِ جنگ کی سختی (۴) اَلْقُوَّۃُ قوت.قرآن کریم میں آتا ہے وَاَنْزَلْنَا الْحَدِیْدَ فِیْہِ بَاْسٌ شَدِیْدٌ کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں بڑی قوت ہے.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اورتقویٰ کے متعلق اسلامی نقطہء نگاہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور بتایا ہےکہ حقیقی نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اگر غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں نیکی اور تقویٰ کے متعلق بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور مختلف جماعتوں اور مختلف قوموں اور مختلف زمانہ کے لوگوں کے نزدیک نیکی کی تعریف مختلف رہی ہے.غرباء نیکی کی کچھ اور تعریف کرتے ہیں اور اُمراء کچھ اور کرتے ہیں.پھر ممالک کے لحاظ سے بھی نیکی کی تعریف میں اختلاف پایا جاتا ہے.ہندوستان میں حاجی بڑے نیک شمار ہوتے ہیں یہاںتک کہ ایک شخص خواہ صوم و صلوٰۃ اور دوسرے احکام شرعی کا کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو لوگ اس کے مقابلہ میں حاجی کو ترجیح دیںگے خواہ اس نے سفر حج میں اپنے اوقات فضول اور لغو طور پر ہی ضائع کئے ہوں اور حج کرنے کے بعد بھی اپنے اندر کوئی تغیر پیدا نہ کیا ہو.اور صوم و صلوٰۃ کا بھی چنداں پابند نہ ہو.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃو السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک ریل کے سٹیشن پر ایک نابینا بڑھیا بیٹھی تھی کہ ایک شخص نے اس کی چادر اُٹھالی.بڑھیا کو جب پتہ لگا کہ چادر غائب ہے تو اس نے آواز دے کر کہا.کہ بھائی حاجی! مجھ غریب کی چادر کیوں لی ہے؟ میرے پاس تو اَور کوئی کپڑا نہیں میں تو سردی سے ٹھٹھر کر مر جائوں گی.وہ چادر تو اس شخص نے لا کر رکھ دی مگر پوچھا کہ تجھے کس طرح پتہ لگا کہ میں حاجی ہوں.بڑھیا نے جواب دیا کہ ایسے کام حاجی ہی کیا کرتے ہیں.اب دیکھو !وہ عورت اس سے واقف نہ
Page 138
تھی اور نہ اس کی آنکھیں سلامت تھیں مگر اس نے پہچان لیا کہ ایسی سنگدلی حاجی میں ہی پائی جاسکتی ہے لیکن باوجود اس کے پھر بھی عام طور پر ہمارے ملک میںحاجیوں کو بڑا نیک سمجھا جاتا ہے لیکن عرب میں جائو تو وہ لوگ حج کو نیکی قرار نہیں دیںگے بلکہ ان میں نیکی سخاوت کو سمجھا جائےگا.وہ لوگ اگر کسی کی نیکی کی تعریف کریںگے تو کہیں گے کہ فلاں شخص بڑا نیک ہے کیونکہ بڑا سخی ہے.اسی طرح اب یورپ میں اسلام پھیلے تو وہاں روزے کو بڑی نیکی سمجھا جائےگا کیونکہ وہ لوگ کثرت سے کھانے پینے والے ہیں.پس جب ان کو کھانے پینے سے رکنا پڑے گا تو وہ حج اور زکوٰۃ اور نمازوغیرہ احکام شرعی کی بجا آوری کو اعلیٰ نیکی قرار دینے کی بجائے صرف روزہ رکھنے کو سب سے بڑی نیکی قرار دیںگے.پھر ہمارے ملک میں یہ بھی بڑی نیکی خیال کی جاتی ہے کہ کوئی شخص نماز کا پابند ہو.ایسے شخص کے متعلق بھی لو گ کہتے ہیں کہ بڑا نیک ہے کیونکہ نماز کاپا بند ہے.لیکن صحابہؓ کے نزدیک کسی شخص کی نیکی کا معیار محض پابندیٔ نماز نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ نیکی کے اس اعلیٰ مقام پر کھڑے تھے جہاں صرف پابندیٔ نماز کو بڑی نیکی قرار دینا ایسی ہی بات تھی جیسے کہا جائے فلاں شخص بڑا بہادر ہے کیونکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ہے یا فلاں شخص بڑا تیز نظر ہے کیونکہ اس کی ماں جو اس کے پاس بیٹھی تھی اسے اُس نے پہچان لیا ہے.یا فلاں شخص کا معدہ بڑا ہی مضبوط ہے کیونکہ اس نے ایک چنا ہضم کر لیا.پس جیسا کہ بہادری تیز نظری اور مضبوطی معدہ کے یہ معیار نہایت مضحکہ خیز ہیں اسی طرح صحابہؓ کے نزدیک کسی شخص کی نیکی کا معیار محض پابندیٔ نماز مضحکہ خیز تھا.کیونکہ وہ لوگ دین کے لئے بڑی بڑی قربانیاں اور سخت آزمائشوں کو نیکی سمجھتے تھے اور جس شخص میں یہ باتیں زیادہ پاتے تھے اس کو نیک سمجھتے تھے.پس نیک اور نیکی کی تعریف ہر زمانہ ہر ملک اور ہر قوم میں جُدا جُدا اور مختلف رہی ہے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیرنا کوئی نیکی نہیں.اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور اُس کی نماز میں وہ اخلاص نہیں جو حقیقی نماز میں ہوتا ہے تو اسے قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ نیکی منہ کے کسی طرف پھیر لینے کا نام نہیں.بلکہ نیکی نام ہے اس کیفیت کا جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اور ظاہری حرکات اُس کیفیت کا ایک نشان ہیں.پس اگر ان ظاہری حرکات میں وہ چیز نہیں جس کا دل سے تعلق ہے تو یہ ظاہری حرکات کچھ چیز نہیں.محض قبلہ کی طرف رُخ کرنا یا نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا حج کرنا یہ تمام باتیں دلی کیفیت نہ ہونے کے باعث ہیچ ہوجاتی ہیں کیونکہ یہ وہ ہتھیار ہیں جو بغیر اس قلبی کیفیت کے کُند اور ناکارہ ہوتے ہیں.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک شخص کے پاس تلوار تو ہو مگر کُند ہو یا ہتھیار تو ہوں مگر زنگ خوردہ ہوں.پس جس طرح ہتھیاروں کی قیمت ان کی تیزی اور صفائی سے وابستہ ہے اسی طرح ان اعمال کی قدروقیمت خدا تعالیٰ کی نظر میں اُسی وقت ہوتی
Page 139
ہے جبکہ ان کے ذریعے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو.اس آیت میں نیکی کی علامات بیان کی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک حقیقی نیکی کیا چیز ہے ؟ فرماتا ہے مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخلاص اور سوز و گداز کی کیفیت بھی ہونی چاہیے.اگر اس کے نتیجہ میں دُعائوں اور ذکرِ الہٰی کی عادت پیدا نہیں ہوتی، اگر اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی، اگر اس کے نتیجہ میںیتیموں اور غریبوں اور بیکسوں کی محبت ترقی نہیں کرتی تو محض مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا کوئی حقیقت نہیں رکھتا.مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ چند رکوع قبل اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلّی دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ١ۗ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ(البقرة:۱۱۶) یعنی اے مسلمانو! بے شک آج تم کمزور سمجھے جاتے ہولیکن یاد رکھو مشرق و مغرب سب اللہ کا ہی ہے ہم ایک دن ان لوگوں سے حکومت چھین کر تمہیں مشرق و مغرب کا حکمران بنا دیںگے اور تم جس طرف بھی اپنے لشکر لے کر نکلو گے تم اللہ کے وجود کو جلوہ گر پائوگے یعنی قدم قدم پر تمہیں فتوحات نصیب ہوںگی اور قدم قدم پر خدا تعالیٰ تمہارے لئے اپنے نشانات ظاہر فرمائےگا.پس چونکہ مسلمانوں کی دنیوی فتوحات کی پہلے پیشگوئی کی جا چکی ہے جس کے مطابق انہوں نے مشرق و مغرب کا حکمران بننا تھا.اور جب کسی قوم کو دنیوی فتوحات حاصل ہو جائیں تو اس بات کا شدید خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں دنیا کی طرف ہی نہ جھک جائے اور خدا تعالیٰ سے مخلصانہ تعلق جو اس کی فتوحات کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے اس کو نظر انداز نہ کر دے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی اعتقادی اور عملی اصلاح کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.یعنی کامل نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کے ملکوں پر اپنا تسلّط جما لو اور فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے چلے جائو.بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا بھاری انعام ہے مگر کامل نیکی صرف مادی فتوحات کا نام نہیں بلکہ نام ہے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ پر اور قرآن کریم پر اور تمام نبیوں پر سچے دل سے ایمان لانےکا اور کامل نیکی نام ہے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں اور غلاموں کی آزادی کے لئے اپنے اموال خرچ کرنے کا.اسی طرح کامل نیکی نام ہے نمازیں قائم کرنےکا اور زکوٰۃ دینے کا اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کا اور مالی مشکلات اور بیماریوں اور جنگ میں صبر اور استقامت سے کام لینے کا.پس بے شک دنیوی فتوحات بھی حاصل کرو مگر اس بات کو مت بھولو کہ صرف ملکوں پر غلبہ حاصل کرنا تمہارا مقصود نہیں بلکہ تمہارا مقصد اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق پیدا کرنا اور اس کی مخلوق کی سچی خدمت کرنا ہے اور یہی وہ غرض ہے جو ہر وقت
Page 140
تمہاری نظروں کے سامنے رہنی چاہیے.اس کے بعد فرماتا ہے وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ.اس حصۂ آیت کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ’’ نیکی وہ ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا‘‘ لیکن ظاہر ہے کہ یہ معنے درست نہیں.اَلْبِرَّ اسم ہے اور اس کے بعد ایسی خبر آنی چاہیے جو اس کے مطابق ہو.لیکن مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ اس کے مطابق نہیں.اس لئے یہاں بعض الفاظ محذوف سمجھے جائیں گے.چنانچہ نحویوں نے اس کی تین توجیہات کی ہیں.اوّل مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰہِ میں مَنْ سے پہلے بِرُّ کا لفظ محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے کہ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ اٰمَنَ یعنی کامل نیکی تو اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر سچے دل سے ایمان لایا.عربی زبان میں بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے سورۂ یوسف میں آتا ہے وَاسْئَلِ الْقَرْیَۃَ (آیت :۸۳) اس کے لفظی معنے یہ ہیں کہ بستی سے پوچھو.حالانکہ بستی سے کوئی نہیں پوچھا کرتا بلکہ بستی والوں سے پوچھا کرتا ہے.پس جس طرح وَاسْئَلِ الْقَرْیَۃَ سے مراد وَاسْئَلْ اَھْلَ الْقَرْیَۃِ ہے اور اس جملہ میں اھل کا لفظ محذوف ہے.اسی طرح مَنْ اٰمَنَ سے پہلے بِرُّ کا لفظ محذوف ہے.(سیبو یہ جلد اوّل صفحہ۱۰۸) دوسری صورت یہ ہے کہ اَلْبِرُّ کو مصدر سمجھ کر اس کے معنے اسم فاعل کے کئے جائیں اور عبارت کا مفہوم یہ نکالا جائے کہ وَلٰکِنَّ الْبَآرَّ مَنْ اٰمَنَ یعنی بڑا نیک اور محمد رسو ل اللہ ؐ کا کامل متبع وہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر اور کتبِ سماویہ پر اور سارے نبیوں پر ایمان لاتا ہے اور اپنے مال کو باوجود تنگی کے اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے غریبوں میں تقسیم کر تا رہتا ہے.تیسری صورت یہ ہے کہ اَلْبِرُّ کے لفظ سے پہلے ذُوْ کا کلمہ محذوف سمجھا جائے اور عبارت یوں ہو کہ وَلٰکِنْ ذَالْبِرِّمَنْ اٰمَنَ یعنی کامل نیکی رکھنے والا وہ شخص ہے جو اللہ پر ایمان لایا.گویا اس آیت کے مفہوم کو تین صورتیں واضح کرتی ہیں اور آیت کے اگلے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوںصورتیں ہی اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ہیں.کیونکہ اس آیت کے بعد وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا١ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ کے الفاظ آتے ہیں اور اَلْمُوْفُوْنَ حالتِ رفع میں ہے اور اَلصَّابِرِیْنَ حالتِ نصب میں.اگر اَلْبَارَّ مَنْ اٰمَنَ یا ذَاالْبِرِّ مَنْ اٰمَنَ والی ترکیب صحیح سمجھی جائے تو اَلْمُوْفُوْنَ مرفوع نہیں آسکتا.اور اگر بِرُّ مَنْ اٰمَنَ صحیح سمجھا جائے تو اَلصَّابِرِیْنَ حالت نصبی میں استعمال نہیں ہو سکتا.درحقیقت دو مختلف کلمات کو دو صورتوں میں استعمال کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں تینوں صورتیں ترکیب کے لحاظ سے درست ہیں اور تینوں معنے ہی خدا تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہیں.بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کے لئے پہلی شرط جو کسی صورت میں بھی بدل نہیں سکتی یہ ہے کہ انسان کو ایمان باللہ حاصل ہو.
Page 141
کبھی کوئی زمانہ ایسا نہیں آسکتا جس میں یہ کہا جا سکے کہ ایمان باللہ کی اب ضرورت نہیں رہی.دوسرے یوم آخرت پر ایمان ہو.یہ حکم بھی کبھی نہیںبدل سکتا.تیسرے ملائکہ پر ایمان ہو یہ صداقت بھی ہمیشہ سے چلی آئی ہے اور چلی جا ئےگی.چہارم کتاب یعنی وحی الہٰی پر ایمان ہو.اس جگہ الکتاب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے واحد رکھا ہے.اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی ایک کتاب پر بھی ایمان لانا کافی ہے بلکہ الکتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ ساری وحی ءِالہٰی پر ایمان لانے والا ہو.خواہ کسی پہلے زمانہ میں نازل ہو چکی ہو.یا آئندہ نازل ہو.پنجم اسے نبیوں پر ایمان ہو.یہ پانچوں نیکیاں ایسی ہیں جن کے بغیر کبھی کوئی شخص روحانیت کا ادنیٰ سے ادنیٰ مقام بھی حاصل نہیں کر سکتا.اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال کی طرف توجہ کی ہے اور سب سے پہلے مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے مگر اس کے لئے بھی صرف اٰتَی الْمَالَ نہیں فرمایا کیونکہ اگر انسان ناجائز طور پر مال خرچ کر دے تو یہ نیکی نہیں بلکہ بدی ہے.اس لئے اٰتَی الْمَالَ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عَلٰی حُبِّہٖ رکھا اور حُبِّہٖ کی ضمیر مال کی طرف جا سکتی ہے اور اِیْتَائِ مال کی طر ف بھی جا سکتی ہے اور اس شخص کی طرف بھی جا سکتی ہے جسے مال دیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف بھی جا سکتی ہے.پہلی صورت میں اس کے یہ معنے ہوںگے کہ اٰتَی الْمَالَ عَلٰی حُبِّ الْمَالِ یعنی باوجود مال کی محبت کے وہ اُسے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے.دوسری صورت میں اس کے یہ معنے ہیں کہ اٰتَی الْمَالَ عَلٰی حُبِّ اِیْتَاءِ الْمَالِ.یعنی وہ اپنا مال چٹّی سمجھ کر نہ دے بلکہ اُسے صدقہ و خیرات دینے کا شوق ہو.اور وہ اس نیکی میں ایک لذّت محسوس کرتے ہوئے اپنا مال پیش کرے.تیسری صورت میں اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ جسے مال دے اسے ذلیل سمجھ کر نہ دے بلکہ اپنا بھائی سمجھ کر دے.اسی طرح اس کی عادات بگاڑنے کے لئے نہ دے بلکہ اس لئے دے کہ وہ اُسے اچھے کاموں میں لگائے.اورترقی کرے.چوتھی صورت میں اس کے یہ معنے ہیں کہ اٰتَی الْمَالَ عَلٰی حُبِّ اللّٰہِ وہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کے لئے مال دے کوئی دنیوی مفاد یا شہرت اس کے پیچھے کام نہ کر رہی ہو.ان چار شرائط کے ساتھ مال خرچ کرنا کبھی ناپسندیدہ نہیں ہو سکتا.یا یوں سمجھ لو کہ یہ مال خرچ کرنے کے چار مدارج ہیں.پہلا درجہ ادنیٰ ہے جس کی طرف قریب کی ضمیر پھر سکتی ہے.دوسرا درجہ اس سے اعلیٰ ہے.تیسرا درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے اور چوتھا درجہ سب سے اعلیٰ ہے.پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہو اور پھر بھی وہ اسے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے.دوسرا درجہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں روپیہ خرچ کرنے کی اُسے عادت ہو گئی ہو اور اس کا مزہ اس نے چکھا ہوا ہو جس کی وجہ سے وہ خود دلی شوق اور محبت سے اس قسم کی نیکیوں کی تلاش میں رہے.تیسرا درجہ یہ ہے کہ جسے مال دیا جائے اُسے اپنا بھائی سمجھ کر دیا جائے تاکہ وہ اُسے اچھے کاموں میں لگائے اور ترقی کرے لیکن پھر اس سے بھی
Page 142
اوپر ایک اور درجہ ہے اور وہ یہ کہ اس کے اس انفاق میں خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کام کر رہی ہو.وہ اس وجہ سے مال خرچ نہ کرے کہ اسے مال خرچ کرنے کی عادت ہو چکی ہے یا اُسے اپنے غریب بھائیوں سے محبت ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا اس کے پیش نظر ہو اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لئے وہ دوسروں سے حسنِ سلوک کرے.یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اسے صوفیاء نے اتنا بڑھایا ہے کہ ان میں سے بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ ہمیں نہ جنت کی ضرورت ہے نہ دوزخ کی بلکہ صرف خدا تعالیٰ کی ضرورت ہے.اگر خدا تعالیٰ دوزخ میں پڑنے سے ملتا ہو تو ہم اس میں بھی جانے کے لئے تیار ہیں.یہ بہت بلند مقام ہے.کیونکہ اس مقام پر سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی چیز انسان کے سامنے نہیں رہتی صرف خدا ہی خدا رہ جاتا ہے اور اس کا حُسن انسان پر اس قدر مستولی ہو جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چیز اُسے نظر ہی نہیں آتی.اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ خدا کی محبت کے لئے کہاں خرچ کرے.سو اس کی تشریح بھی کر دی اور بتایا کہ (۱) وہ قرابت والوں کو دے اس لئے کہ انسان پر ان کا بڑا حق ہوتا ہے.مثلاً ماں باپ ہیں جو بچوں کی پرورش اور ان کی نگہداشت کے لئے اتنی بڑی قربانیاں کرتے ہیں جن کی مثال کسی اور جگہ نہیں مل سکتی.اسی طرح دوسرے رشتہ دار اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ اگر وہ حاجت مند ہوںتو ان کی امداد کی جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے.(۲) پھر فرمایا کہ وہ یتامیٰ کو دے چونکہ ان کی خبر گیری کرنےوالا کوئی نہیں ہوتا اس لئے ان کے حقوق کو مدِّنظر رکھنے کی تعلیم دی.(۳) تیسرے نمبر پر مساکین کو رکھا جن کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مال بھی نہیں ہوتا.اور وہ لوگوں کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرتے.گویا وہ اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں کہلَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا (البقرة:۲۷۴).وہ غربت کے باوجود اپنے اندر اخلاقی بلندی رکھتے ہیں اور اپنے و قار کو قائم رکھنے کے لئے دوسروں سے مانگنے کی ذلت برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے.(۴) چوتھے نمبر پر مسافر کو رکھا.اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے غربت کی شرط نہیں لگائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں غریب مسافروں کی امداد کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں اگر کسی آسودہ حال مسافر کی مدد کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے وہ مالدار تو ہو مگر راستہ میں اس کا مال ضائع ہو گیا ہو.اگر ایسا ہو تو وہ بطور حق بھی لے سکتا ہے اور کوئی چیز گرو رکھ کر بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے.اسی طرح حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ملکی اور غیر ملکی مسافروں اور سیاحوں کے لئے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائے اور ان کی مشکلات کو دُور کرنے کی کوشش کرے.اس کے بعد پانچویں نمبر پر سائل کو رکھا.اس کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ غریب اور مفلس ہے تو اُسے ابن السبیل کے بعد
Page 143
کیوں رکھا ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے سوال کرنا پسندیدہ قرار نہیں دیا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور پھر بھی وہ سوال کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے(ابوداؤدکتاب الزکٰوة من یوتی من الصدقۃ ) اسی طرح حضرت عمررضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک سائل کو دیکھا جس کی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی اور پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور آپ نے اس سے آٹا چھین کر اونٹوں کے آگے ڈال دیا اور فرمایا.اب مانگ.(سیرت عمر ابن الخطاب لابن المجوزی باب ۶۰ صفحہ ۱۷۰) آپ کی اس سے غرض یہ تھی کہ وہ لوگوں کے لئے بار نہ بنے بلکہ خود کام کرے اور دوسروں سے مانگ کر کھانے کی ذلّت سے بچے.پس چونکہ اسلام نے مانگ کر کھانا ناپسند کیا ہے اس لئے یہ بتانے کےلئے کہ سوال کرنا ایک ناپسندیدہ امر ہے سائل کو سب سے آخر میں رکھا.اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں اعلیٰ درجہ کے اخلاق پیدا ہوں اور بجائے اس کے کہ لوگ سوال کرتے پھریں.وہ خود لوگوں کی ضروریات کا پتہ لگا کر ان کو پورا کیا کریںتاکہ ان کے لئے سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے.وَ فِي الرِّقَابِ.آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر روپیہ خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے جو قید میں پڑے ہوئے ہوں.اس جملہ میں ایک مضاف محذوف ہے جو فَکٌّ کا لفظ ہے.یعنی اصل عبارت یوں ہے کہ وَفِیْ فَکِّ الرِّقَابِ.اس گروہ کو پیچھے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں زیادہ تر غیر مذاہب کے ہی قیدی ہو سکتے ہیں.اور قاعدہ ہے کہ اقرب کا حق دوسروں سے مقدم ہوتا ہے.ابن السبیل کو تو مہمان کے طور پر رکھا ہے کہ خواہ وہ کافر ہو اُسے بھی دو مگر قیدی تو ایسے ہی لوگ ہوںگے جو مسلمانوں کے مقابلہ میںلڑائی کے لئے آئے ہوںگے اس لئے فِي الرِّقَابِ کو بعد میں رکھا.لیکن یہ بھی اسلام کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اُسی شخص کے متعلق جو مسلمانوں کو مارنے کے لئے آیاتھا کہتا ہے کہ اسے روپیہ دے کر آزاد کرادو.اسی طرح فِي الرِّقَابِ میں قرضدار اور ضامن کو امداد دینا بھی شامل ہے.حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر قسم کے صدقات دیئے لیکن غلام آزاد کرنے کاموقعہ نہیں ملا.میں جب حج کے لئے مکہ گیا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اگر سو دو سو روپیہ میں کوئی غلام مل جائے تو میری طرف سے آزاد کر دینا مگر مجھے کوئی غلام نہ ملا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی بھی توفیق عطا فرما دی.چنانچہ مرزا محمد اشرف صاحب محاسب صدر انجمن احمدیہ کی روایت ہے کہ حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ نے دو غلام آزاد کر وا دیئے تھے.
Page 144
پھر فرماتا ہےوَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ کامل نیک وہ شخص ہے جس نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دی.صلوٰۃ اور زکوٰۃ کے وسیع معنے ہیں.مگر شریعت نے ان کو اپنی ایک مخصوص اصطلاح بھی بنا لیا ہے اس جگہ صلوٰۃ اور زکوٰۃ سے اصطلاحی نماز اور زکوٰۃ ہی مراد ہے.جن میں سے ایک خدا اور انسان کے تعلقات کو استوار کرتی اور دوسری انسان اور انسان کے باہمی تعلقات میں رابطہ قائم کرتی ہے.اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ صرف مال خرچ کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے بلکہ تمہارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو.گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد کو جب تک ایک منظّم رنگ میں ادا نہ کیا جائے اُس وقت تک انسان نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتا.پھر فرمایا وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا١ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ.نیکی اورتقویٰ کا اعلیٰ مقام جن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ معاہدات کی پابندی کرتے ہیں اور اگر لوگ ان پر سختی کریں یاظلم سے کام لیں تو وہ صبر سے کام لیتے ہیں.گویا ایک طرف تو وہ اسلامی تمدن کو قائم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور کبھی بدعہدی یا دھوکا بازی سے کام نہیں لیتے اور دوسری طرف اگر مذہبی قومی اور ملکی ضروریات کے لئے انہیں سختیاں بھی برداشت کرنی پڑیں تو وہ استقلال کے ساتھ ان کو برداشت کرتے ہیں اور استقامت کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں.اس جگہ عہد سے مراد صرف زبانی عہد ہی نہیں بلکہ تمدن سے تعلق رکھنے والے تمام اہم مسائل بھی اس میں شامل ہیں.کیونکہ متمدّن دنیا میں ایک دوسرے کے حقوق کی اسی رنگ میں حفاظت ہوتی ہے کہ ہر شخص سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دائرہ سے تجاوز نہ کرے اور دوسروں کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش نہ کرے اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو تمدن کو قائم کرنے والے سمجھے جاتے ہیں اور اگر اس کے خلاف عمل کریں تو فتنہ و فساد پیدا کرنے والے قرار پاتے ہیں.اسلام چونکہ صلح و آشتی اور محبت کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے اس لئے اس نے کامل الایمان لوگوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ معاہدات کی سختی سے پابندی کرتے ہیں.لیکن اس کے ساتھ ہی بتایا کہ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ.وہ فقرو فاقہ اور تنگیوں میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں اور جسمانی دکھوں اور مصائب میں بھی صبر سے کام لیتے ہیں.اس جگہ الْبَاْسَآءِ سے مالی مشکلات اور ضَرَّاء سے جسمانی مشکلات اور امراض وغیرہ مراد ہیں اور بَاْ س سے شدتِ حرب مراد ہے.گویا ادنیٰ سے اعلیٰ ابتلائوں کی طرف ترقی کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے.یہ لڑائیاں جن کا اس جگہ ذکر کیا گیا ہے دو قسم کی ہو سکتی ہیں ایک وہ جو بھائیوں بھائیوں میں ہوں اور دوسری وہ جو غیروں سے ہوں.اگر آپس میں جھگڑا ہو تو وہ
Page 145
اَلصَّابِرِیْنَ فِی الْبَاْسَآئِ وَ الضَّرَّآئِ کے مطابق اپنے حقوق کو خود چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور سچے ہو کر جھوٹوں کا ساتذ لّل اختیار کرتے ہیں اور اگر غیروں سے ہو تو وہ بھاگتے نہیں بلکہ دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے اور قیام امن کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتے ہیں.اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا.فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدق و وفا کا نمونہ دکھایا.وَ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ اور یہی لوگ مصائب اور دکھوں سے نجات پانے والے ہیں.ان کی یہ خصوصیت اس لئے بیان کی کہ انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اپنے حقوق کو پامال ہوتے دیکھ کر ہوتی ہے.دوسرے سے حسن سلوک کو تو وہ احسان سمجھتا ہے مگر جب کوئی شخص اُسے دکھ پہنچاتا ہے تو وہ اپنی ہتک محسوس کرتا ہے.پس چونکہ یہ ان کی غیر معمولی قربانی تھی کہ انہوں نے خدا کے لئے دوسروں کے مظالم سہے اس لئے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو میں خصوصیت کے ساتھ پیش کرتا ہوں.یہ سچے اور راستباز لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو عملی طور پر سچا کر کے دکھا دیا ہے.اور یہی وہ لوگ ہیں جو مصائب سے بچنے والے ہیں.کیونکہ مصائب اگر آسمانی ہوں تو اُن کا علاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں اور اگر تمدنی مصائب ہوں تو ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ تمدنی قوانین کو مدِّنظر رکھیں.اور یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر بھی عمل کرنے والے ہیں اور تمدنی خرابیوں سے بھی بچنے والے ہیں.پس یہ لوگ دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے.جو قوم ذلیل یاہلاک ہو گی وہ یا تو خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر ہلاک ہو گی یا تمدنی قوانین کو نظر انداز کر کے اپنی ہلاکت مول لے گی.يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ١ؕ اے لوگو!جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں کے بارہ میں برابر کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے.آزا د (قاتل )آزاد اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى١ؕ فَمَنْ (مقتول)کے بدلہ میں.غلام (قاتل) غلام (مقتول ) کے بدلہ میں.عورت (قاتل) عورت (مقتولہ) کے بدلہ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ میں(قصاص کی مستحق )ہے.جس(قاتل) کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کردیا جائے تو (مقتول کا
Page 146
اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ١ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ١ؕ وارث بقیہ تاوان کو صرف) مناسب طور پر وصول کر سکتا ہےاور (قاتل پر)عمدگی کے ساتھ (بقیہ تاوان )اس کو ادا کر فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۰۰۱۷۹ دینا (واجب )ہے.یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے.پھر جو شخص اس (حکم) کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لئے درد ناک عذاب (مقدر)ہے.حلّ لُغات.اَلْقِصَاصُ اَنْ یُّفْعَلَ بِہٖ مِثْلَ مَا فَعَلَہٗ مِنْ قَتْلٍ اَوْقَطْعٍ اَوْضَرْبٍ اَوْ جُرْحٍ (لسان) عربی زبان میں قصاص کے معنے یہ ہیں کہ کسی شخص سے وہی سلوک کیا جائے جو اس نے قتل یا قطع یا ضرب یا زخم کرنے کی صورت میں دوسرے سے کیا ہے.تاج العروس میں لکھا ہے اَلْقِصَاصُ اَلْقَتْلُ بِالْقَتْلِ وَالْجُرْحُ بِالْجُرْحِ کہ قصاص اس چیز کا نام ہے کہ قتل کے مقابلہ میں قتل اور زخم کے مقابلہ میں زخم کیا جائے.تَخْفِیْفٌ کے معنے (۱) سہولت اور( ۲) معافی کے ہیں.تفسیر.بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے قتل کے بارہ میں جوکچھ بیان کیا ہے صرف بائیبل کے تتبّع میں کیا ہے خود اصولی رنگ میں اس بارہ میں کوئی ہدایت نہیں دی.ان کے نزدیک یہودیوں کو جو یہ کہا گیا تھا کہ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ١ۙ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَ الْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ١ۙ وَ الْجُرُوْحَ قِصَاصٌ(المائدة:۴۶) یعنی جان کے بدلہ میں جان اور آنکھ کے بدلہ میں آنکھ اور ناک کے بدلہ میں ناک اور کان کے بدلہ میں کان اور دانت کے بدلہ میں دانت اور زخموں کے بدلہ میں زخم برابر کا بدلہ ہیں اس حکم کو قرآن کریم نے اس جگہ دُہرا دیا ہے مگر ان کا یہ خیال محض قلّتِ تدبّر کا نتیجہ ہے.میرے نزدیک بنی نوع انسان کی مذہبی، سیاسی، تمدنی اور عائلی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں جسے اسلام نے پوری وضاحت کے ساتھ بیان نہ کیا ہو.بیشک وہ پہلے مذاہب کی تعلیموں کا بھی بعض مقامات پر ذکر کرتا ہے مگر نفس مسئلہ پروہ پہلے خود روشنی ڈالتا ہے اور اس کے متعلق ایک جامع اور کامل تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس کے بعد وہ غیر مذاہب والوں پر حجت تمام کرنے یا انہیں شرمندہ کرنے کے لئے ان کی تعلیموں کو بھی ان کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ ان کے دلوں میں یہ
Page 147
احساس پیدا ہو کہ مذہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے انہوں نے اس کے احکام کو کس طرح پسِ پشت پھینک رکھا ہے.اس جگہ بھی قصاص کی بنی نوع انسان کو جو تعلیم دی گئی ہے یہ یہودیوں کی اتباع میں نہیں دی گئی بلکہ ان احکام کے سلسلہ میں دی گئی ہے جو اکیسویں رکوع سے دئیے جا رہے ہیں.چنانچہ دیکھ لو پچھلی آیات میں بتلایا گیاتھا کہ کامل الایمان لوگوں کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ وہ بَاْسَآئَ میں بھی صبر کرتے ہیں اور ضَرَّآئَ میں بھی صبر کرتے ہیں اور حِیْنَ البَاْس بھی صبر کرتے ہیں یعنی خواہ ان پر مالی مشکلات آئیں اور فقروفاقہ تک ان کی نوبت پہنچ جائے تب بھی وہ جادۂ استقامت پر قائم رہتے ہیں اور خواہ جسمانی مشکلات آئیں اور بیماریاں ان کو گھیر لیں تب بھی وہ صبر کرتے ہیں.اور خواہ لڑائیوں میں مارے جائیں تب بھی وہ دشمن سے مرعوب نہیں ہوتے.اس پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر یہ صبر کا سلسلہ کب تک چلے گا.کیا لوگ ہمیں مارتے ہی چلے جائیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں اور اگر ایسا ہو تو ہماری زندگی کی کیا صورت ہو گی؟ اس لئے فرمایا کہ تمہارا کام تو یہی ہے کہ تم صبر کرو لیکن کچھ اور لوگ جن کے سپرد حکومت کا نظام کیا گیا ہے ان کا فرض ہے کہ وہ ایسے ظالموں سے بدلہ لیں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں چنانچہ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى میں انہی لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور کہا گیاہے کہ تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے اس جگہ ’’تم‘‘سے صرف حکّام مراد ہیں جو لاء اینڈ آرڈر یعنی نظم و ضبط کے ذمہ وار ہوتے ہیں عام لوگ مراد نہیں.اور کُتِبَ کہہ کر بتایا ہے کہ حکّام کا فرض ہے کہ وہ قصاص لیں.حکّام کو یہ اختیار نہیں کہ وہ معاف کر دیں.اَلصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ میں تو عوام مخاطب تھے مگر کُتِبَ عَلَیْکُمْ میں صرف حکام سے خطاب کیا گیا ہے کہ وہ قصاص لیں.اور فِی الْقَتْلٰی کہہ کر تصریح کر دی گئی ہے کہ اس میں جروح شامل نہیں.اور درحقیقت یہی وہ آیت ہے جس میں قتل کی سزا کے متعلق اسلامی تعلیم بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہے.اور یہ عام حکم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فِی الْقَتْلٰی فرمایا ہے کہ مقتولوں کے متعلق یہ حکم ہے یہ کوئی سوال نہیں کہ وہ مقتول کون ہو اور کس قوم سے تعلق رکھتا ہو؟ اس آیت کے سوا قتل ِ عمد کی دنیوی سزا کا ذکر قرآن کریم کی کسی اور آیت میں نہیں ہے پس یہی آیت ہے جس پر اسلامی فقہ کی بنیاد ہے اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا.نہ اس میں یہ ذکر ہے کہ کس کس آلہ سے قتل کرنے والے کی سزا قتل ہے بلکہ خواہ کسی آلہ سے کوئی شخص قتل کرے.اُس کو قتل کیا جائےگا.بلکہ حدیثوں سے تو یہاں تک ثابت ہے کہ ایک قتل کے کیس میں بعض دفعہ ایک سے زیادہ افراد کو بھی مارا گیا.چنانچہ لکھا ہے کہ صَنْعَاء میں ایک شخص کو کئی لوگوں نے مل کر قتل کر دیا.حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب کو جو تعداد میں سات تھے قتل کروادیا اور فرمایا کہ اگر سارا شہر قتل میں شریک ہوتا تو میں سب کو قتل
Page 148
کرادیتا.(مؤطا کتاب العقول باب ما جاء فی العیلۃ والسحر ) اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ لَایَحِلُّ دَمُ اِمْرِءٍ مُسْلِمٍ یَشْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ اِلَّابِـاِحْدَیْ ثَلَاثٍ اَلثَّیِّبُ الزَّانِیْ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِکُ لِدِیْنِہٖ اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَا عَۃِ (مسلم کتاب القسامة والقصاص باب ما یباح بہ دم المسلم) یعنی صرف تین گناہ ایسے ہیں جن کی بنا پر مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے.اوّل.شادی شدہ شخص ہو اور پھر زنا کرے.دوم.کوئی شخص قاتل ثابت ہو جائے.سوم.جو شخص اسلام کو چھوڑ کر جماعت مسلمہ سے الگ ہو جائے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح مسلم میں تو صرف یہی الفاظ بیان کئے گئے ہیں مگر نسائی میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنَ الْاِسْلَامِ یُحَارِبُ اللّٰہَ عَزَّ وَجَلَّ وَ رَسُوْلَہٗ فَیُقْتَلُ اَوْ یُصَلَّبُ اَوْ یُنْفٰی مِنَ الْاَرْضِ.(النسائی کتاب تحریم الدم باب الصلب ) یعنی وہ شخص جو اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں سے جنگ شروع کر دے.اس کے متعلق جائز ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے یا صلیب پر لٹکا دیا جائے یا اُسے جلا وطن کر دیا جائے.یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورت مرد کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ جو بھی قتل کرےگا اسے قتل کیا جائےگا اور جان کے بدلہ جان لی جائےگی.اسی طرح مسند احمد بن جنبل، بخاری، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُعَاھِدًا لَمْ یَرِحْ رَائِـحَۃَ الْجَنَّۃِ (ابن ماجہ کتاب الدّیات باب من قتل معاھدا) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کافر معاہد کو مار دے وہ جنّت کی خوشبو نہیں سونگھے گا.اور یہی سزا قرآن کریم میں ایک مسلمان کے قاتل کی بیان کی گئی ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا(النساء: ۹۴) یعنی جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہو گی وہ اس میں دیر تک رہتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گا اور اُسے اپنے قرب سے محروم کر دےگا اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کرےگا.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس کی تائید کرتا ہے.چنانچہ ابو جعفر طحاوی اپنی کتاب ’’شرح معانی الآثار‘‘ میں لکھتے ہیں اِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اُتِیَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ قَدْ قَتَلَ مُعَاھِدًا مِنْ اَھْلِ الذِّمَّۃِ فَاَمَرَ بِہٖ فَضُرِبَ عُنُقُہٗ وَقَالَ اَنَا اَوْلٰی مَنْ وَفٰی بِذِ مَّتِہٖ (شرح معانی الآثار کتاب الجنایات باب المؤمن یقتل الکافر متعمدا)یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسلمان لایا گیا جس نے ایک معاہد کا فر کو جو اسلامی حکومت کی رعایا بن چکا تھا قتل کر دیا تھا.آپ نے اس کے قتل کئے جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں عہد پورا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عہد کی نگہداشت رکھنے والا ہوں اسی طرح طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت روایت کی
Page 149
ہے کہ ایک مسلمان نے ایک ذمّی کو قتل کر دیا تو آپ نے اس مسلمان کے قتل کئے جانے کا حکم دے دیا.بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لَا یُقْتَلُ مُوْمِنٌ بِکَافِرٍ کہ کوئی مومن کسی کافر کے بدلہ میں قتل نہیں کیا جائےگا.مگر ساری حدیث دیکھنے سے بات حل ہو جاتی ہے.حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں کہ لَا یُقْتَلُ مُوْمِنٌ بِکَافِرٍ وَلَا ذُوْعَھْدٍ فِیْ عَھْدِہٖ (ابن ماجہ کتاب الدیات باب لا یقتل مسلم بکافر).اس حدیث کا یہ دوسرا فقرہ کہ وَلَاذُوْ عَھْدٍ فِیْ عَھْدِہٖ اس کے معنوں کو حل کر دیتا ہے اگر اس کے یہ معنے ہوں کہ کافر کے بدلہ میں مسلمان نہ مارا جائے تو پھر ذُوْ عَھْدٍ کے یہ معنے کرنے ہوںگے کہ وَلَا ذُوْ عَھْدٍ بِکَافِرٍ کہ کسی ذوعہد کو بھی کافر کے بدلہ میں قتل نہ کیا جائے.حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا.پس یہاں کافر سے مراد محارب کافر ہے نہ کہ عام کافر.تبھی فرمایا کہ ذمّی کافر بھی محارب کافر کے بدلہ میں نہیں مارا جائےگا.اب ہم صحابہؓکا طریق عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ بھی غیر مسلم کے مسلم قاتل کو قتل کی سزا ہی دیتے تھے.چنانچہ طبری جلد ۵ صفحہ ۴۴میں قماذبان ابن ہر مزان اپنے والد کے قتل کا واقعہ بیان کرتاہے.ہرمزان ایک ایرانی رئیس اور مجوسی المذہب تھا اور حضرت عمر ؓ خلیفہ ثانی کے قتل کی سازش میں شریک ہونےکا شبہ اس پر کیا گیا تھا.اس پر بلا تحقیق جوش میں آکر عبید اللہ بن عمرؓ نے اس کو قتل کر دیا وہ کہتا ہے کَانَتِ الْعَجْمُ بِالْمَدِیْنَۃِ یَسْتَرُوْحُ بَعْضُھَا اِلیٰ بَعْضٍ فَـمَرَّ فَیْرُوْز بِاَبِیْ وَمَعَہٗ خَنْجَرٌ لَہٗ رَأْسَانِ فَتَنَاوَلَہٗ مِنْہُ.وَقَالَ مَاتَصْنَعُ بِھٰذَافِیْ ھٰذِہِ الْبِلَادِ فَقَالَ اَ بُسُّ بِہٖ فَرَاٰ ہُ رَجُلٌ فَلَمَّا اُصِیْبَ عُمَرُ قَالَ رَاَیْتُ ھٰذَا مَعَ الْھُرْمَزَانِ دَفَعَہٗ اِلٰی فَیْرُوْزَ فَاَقْبَلَ عُبَیْدُ اللّٰہِ فَقَتَلَہٗ فَلَمَّاوُ لِّیَ عُثَمَانُ دَعَانِیْ فَاَمْکَنَنِیْ مِنْہُ ثُمَّ قَالَ یَا بُنَیَّ ھٰذَا قَاتِلُ اَبِیْکَ وَاَنْتَ اَوْلٰی بِہٖ مِنَّا فَاذْھَبْ فَاقْتُلْہُ فَخَرَجْتُ بِہٖ وَ مَافِی الْاَرْضِ اَحَدٌ اِلَّا مَعِیَ اِلَّا اِنَّھُمْ یَطْلُبُوْنَ اِلَیَّ فِیْہِ فَقُلْتُ لَھُمْ أَلِیْ قَتْلُہٗ قَالُوْا نَعَمْ وَسَبُّوْا عُبَیْدَ اللّٰہِ فَقُلْتُ اَفَلَکُمْ اَنْ تَمْنَعُوْہُ قَالُوْا لَا وَسَبُّوہُ فَتَرَکْتُہٗ لِلّٰہِ وَلَھُمْ.فَا حْتَمَلُوْنِیْ فَوَ اللّٰہِ مَابَلَغْتُ الْمَنْزِلَ اِلَّا عَلٰی رُئُ وْسِ الرِّجَالِ وَاَکُفِّھِمْ.(تاریخ الطبری،سنۃ ۲۴ ھ) اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایرانی لوگ مدینہ میں ایک دوسرے سے ملے جُلے رہتے تھے (جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دوسرے ملک میں جاکر وطنیت نمایاں ہو جاتی ہے) ایک دن فیروز (قاتلِ عمرؓ خلیفہ ثانی) میرے باپ سے ملا اور اس کے پاس ایک خنجر تھا جو دونوں طرف سے تیز کیا ہوا تھا.میرے باپ نے اس خنجر کو پکڑ لیا اور اس سے دریافت کیا کہ اس ملک میں تو اس خنجر سے کیا کام لیتا ہے(یعنی یہ ملک تو امن کا ملک ہے اس میں ایسے ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے؟) اُس نے کہا کہ میں اس سے اونٹ ہنکانے کا کام لیتا ہوں.جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اُس وقت
Page 150
کسی نے ان کو دیکھ لیا اور جب حضرت عمرؓ مارے گئے تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خود ہر مزان کو یہ خنجر فیروز کو پکڑاتے ہوئے دیکھا تھا.اِس پر عبید اللہ(حضرت عمرؓ کے چھوٹے بیٹے)نے جا کر میرے باپ کو قتل کر دیا.جب حضرت عثمانؓ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور عبیداللہ کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے! یہ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تو ہماری نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے پس جا اور اس کو قتل کر دے میں نے اس کو پکڑ لیا اور شہر سے باہر نکلا.راستہ میں جو شخص مجھے ملتا میرے ساتھ ہو جاتا لیکن کوئی شخص مقابلہ نہ کرتا.وہ مجھ سے صرف اتنی درخواست کرتے تھے کہ میں اسے چھوڑ دوں.پس میں نے سب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میرا حق ہے کہ میں اسے قتل کردوں؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں تمہارا حق ہے کہ اسے قتل کر دو اور عبیداللہ کو بھلا بُرا کہنے لگے کہ اس نے ایسا بُرا کام کیا ہے پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں کو حق ہے کہ اسے مجھ سے چھڑالو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اور پھر عبیداللہ کو بُرا بھلا کہا کہ اس نے بلاثبوت اس کے باپ کو قتل کر دیا.اس پر میں نے خدا اور ان لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا.اور مسلمانوں نے فرطِ مسرت سے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھالیا اور خدا تعالیٰ کی قسم! میں اپنے گھر تک لوگوں کے سروں اور کندھوں پر پہنچا اور انہوں نے مجھے زمین پر قدم تک نہیں رکھنے دیا.اس روایت سے ثابت ہے کہ صحابہؓ کا طریق عمل بھی یہی رہا ہے کہ وہ غیر مسلم کے مسلم قاتل کو سزائے قتل دیتے تھے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کسی ہتھیار سے کوئی شخص مارا جائے وہ مارا جائےگا.اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزا دینے والی حکومت ہی ہے.کیونکہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عبیداللہ بن عمرؓ کو گرفتار بھی حضرت عثمانؓ نے کیا اور اس کو قتل کے لئے ہرمزان کے بیٹے کے سپرد بھی انہوں نے ہی کیا.نہ ہرمزان کے کسی وارث نے اس پر مقدمہ چلایا اور نہ اس نے گرفتار کیا.اس جگہ اس شبہ کا ازالہ کردینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا دینے کے لئے آیا مقتول کے وارثوں کے سپر دکرنا چاہیے جیسا کہ حضرت عثمانؓ نے کیا یا خود حکومت کو سزا دینی چاہیے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ ایک جزوی معاملہ ہے اس لئے اس کو اسلام نے ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق عمل کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے.قوم اپنے تمدن اور حالات کے مطابق جس طریق کو زیادہ مفید دیکھے اختیار کر سکتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں طریق ہی خاص خاص حالات میں مفید ہوتے ہیں.اس کے بعد فرماتا ہےاَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى.آزاد آزاد کے بدلہ میں.غلام غلام کے بدلہ میں اور عورت عورت کے بدلہ میں قتل کی جائے.اس سے یہ مراد نہیں کہ آزاد مقتول کے بدلہ میں کسی آزاد کو
Page 151
ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی غلام ہی ہو.اور غلام مقتول کے بدلہ میں کسی غلام کو ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی حُرّ ہو اور عورت مقتول کے بدلہ میں کسی عورت کو ہی قتل کیا جائے خواہ اس کا قاتل کوئی مرد ہو کیونکہكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى میں حکم پہلے بیان ہوچکا ہے.درحقیقت یہ جملہ مستأنفہ ہے اور جملہ مستانفہ اس لئے آتا ہے کہ پہلے جملہ میں جو سوال مقدّر ہو اس کو بیان کئے بغیر نئے جملہ میں جواب دیا جائے اور بغیر عطف کے اس کو بیان کیا جائے(شرح مختصر معانی مؤلفہ ابن یعقوب و بہائوالدین جلد۳ مطبوعہ مصر صفحہ۵۴) اس جگہ بھی یہ جملہ ایک سوال مقدّر کے جواب کے لئے لایا گیا ہے.اور اس میں عرب کی ان رسوم کا قلع قمع کیا گیا ہے جو ان میں عام طور پر رائج تھیں.اور وہ سوال مقدّر یہ ہے کہ کیا اس حکم سے عرب کا پہلا طریق موقوف ہو جائےگا؟ سو فرمایا کہ ہاں اور اس کی چند مثالیں بیان کر دیں کہ یہ سب موقوف ہیں.چنانچہ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى میں ان کی صرف چندمثالیں بیان کی گئی ہیں نہ کہ کل رسوم.گویا ھَلُّمَ جَرًّا کی طرح کا یہ فقرہ ہے اور مراد یہ ہے کہ اس حکم کے ذریعہ وہ تمام امتیاز مٹا دیئے گئے ہیں جو زمانۂ جاہلیت میں رائج تھے.اصل بات یہ ہے کہ عربوں میں بعض خاندانوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا اور بعض کو چھوٹا.بعض کو آزاد سمجھا جاتا تھا اور بعض کو غلام اور جب کسی سے کوئی جرم سرزد ہوتا تو وہ لوگ یہ دیکھاکرتے تھے کہ آیا مجرم غلام ہے یا آزاد.اور اگر غلام ہے تو کسی بڑے آدمی کا غلام ہے یا چھوٹے کا.مرد ہے یا عورت.اعلیٰ خاندان میں سے ہے یا ادنیٰ خاندان میں سے امیر ہے یا غریب.اور سزا میں ان تمام امور کو ملحوظ رکھا جاتا اور آزاد مردوں اور عورتوں کو وہ سزائیں نہ دی جاتیں جو غلام مردوں اور عورتوں کو دی جاتی تھیں.اسی طرح اعلیٰ خاندانوں کے افراد کو وہ سزائیں نہیں دی جاتی تھیں جو ادنیٰ خاندانوں کے افراد کو دی جاتی تھیں.چونکہ اسلام نے كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى میں یہ عام حکم دے دیا تھا کہ ہر ایک شخص جو قتل کیاجائے اس کا قاتل لازماً قتل ہو خواہ عورت مرد کو مارے یا مرد عورت کو مارے.خواہ آزاد غلام کو مارے یا غلام آزاد کو مارے.خواہ ایک شخص کو جماعت مارے اور خواہ کافر معاہد کو مسلمان مارے اس لئے طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آئندہ قصاص کیا پہلے طریق پر بھی جو جاہلیت میں رائج تھا لیا جائےگا یا نہیں.سو اس کا جواب دیا کہ نہیں اور ہرگز نہیں.وہ امتیازات اب مٹائے جاتے ہیں.اور اس کے لئے صرف تین مثالیں دے دیں.باقی مثالیں اس نے چھوڑ دی ہیں.کیونکہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ اگر کسی جگہ تین مثالیں بیان ہوں.تو اس جگہ ھَلُمَّ جَرًّا ساتھ مل جاتا ہے اور سب مثالیں انہی تین مثالوں میں شامل سمجھی جاتی ہیں.اس جگہ بھی تین مثالوں سے مراد ہر قسم کی مثال ہے اور یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خواہ قاتل حُراور مقتول عبد ہو یا قاتل مرد اور
Page 152
مقتول عورت ہو یا قاتل عورت اور مقتول مرد ہو جو بھی قتل کرے اسے قتل کی سزا دو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے.آپ ؐنے ایک عورت کے بدلہ میں مرد کوقتل کیا(مسلم کتاب القصاص باب ثبوت القصاص فی القتل بالحجر وغیرہ ) اسی طرح غلام کے بدلہ میں آزاد کے مارے جانےکا حکم دیا.جیسے سمرۃ ابن جندب کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَنْ قَتَلَ عَبْدَہُ قَتَلْنَا ہُ وَمَنْ جَدَعَہٗ جَدَعْنَا ہُ (ابن ماجہ ابواب الدیات باب ھل یقتل الحر بالعبد) یعنی جوشخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے اس کے بدلہ میں قتل کریں گے اور جوشخص اپنے غلام کے ہاتھ پائوں کاٹے گا.ہم اس کے بدلہ میں اس کے ہاتھ پائوں کاٹیں گے.اس کے بعد فرماتا ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ یعنی اگر کسی مقتول کے وارث کسی مصلحت کے ماتحت قاتل کو اس کے جرم کا کچھ حصہ معاف کر دیں تو ان کو اختیار ہے.بعض لوگ اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ حکومت کو قاتل کے گرفتار کرنے یا اس کو سزا دینے کا کوئی اختیار نہیں بلکہ یہ تمام اختیار مقتول کے ورثاء کو حاصل ہے.مگر یہ درست نہیں اس جگہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء احسان کے طور پر قاتل کو معاف کر دیں تو حکومت کو اُن کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے اس حقِّ معافی کے سوا رشتہ داروں کا کوئی تعلق قاتل کے ساتھ نہیں.قاتل کو گرفتار کرنا یا اس پر مقدمہ چلانا حکومت ہی کاکام ہے اور اُسی کے ذمہ ہے جیسا کہكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى میں حکومت کے ذمّہ وار افسران کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ وہ قتل کے واقعات کی چھان بین کریں اور مجرم کو قرار واقعی سزا دلوائیں.اسلام نے مقتول کے وارثوں کو عفو کا جو اختیار دیا ہے اس کے متعلق کہاجا سکتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ نقصانات کا بھی احتمال ہو سکتا ہے.مثلاً ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے وارث ہی قتل کروا دیں اور پھر قاتل کو معاف کردیں.یہ شبہ ایک معقول شبہ ہے.مگر اسلام نے اس قسم کے خدشات کا بھی ازالہ کر دیا ہے اور گو ایک طرف اس نے دو مخالف خاندانوں میں صلح کرانے کے لئے عفو کی اجازت دی ہے مگر دوسری طرف ایسی ناجائز کارروائیوں کی بھی روک تھام کر دی ہے.چنانچہ عفو کے ساتھ اس نے اصلاح کی شرط لگا دی ہےجس کے معنے یہ ہیں کہ عفو اسی وقت جائز ہوتا ہے جب اس کے نتیجہ میں اصلاح کی اُمید ہو.اگر عفو باعثِ فساد ہے تو ایسا عفو ہرگز جائز نہیں اور حکومت باوجود وارثوں کے عفو کر دینے کے اپنے طور پر سزا دے سکتی ہے.اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ جو طبری نے لکھا ہے بتاتا ہے کہ ابتدائے اسلام سے اس احتیاط پر عمل ہوتا چلا آیا ہے وہ واقعہ اس طرح ہے کہ
Page 153
عدل بن عثمان بیان کرتے ہیں.رَاَیْتُ عَلِیًّا عَمَّ خَارِجًا مِنْ ھَمْدَانَ فَرَأَی فِئَتَیْنِ تَقْتُلَانِ فَفَرَّقَ بَیْنَھُمَا ثُمَّ مَضٰی فَسَمِعَ صَوْتًا یَا غَوْثًابِاللّٰہِ فَخَرَجَ یَحُضُّ نَحْوَہٗ حَتّٰی سَمِعْتُ خَفْقَ نَعْلِہٖ وَھُوَ یَقُوْلُ اَتَاکَ الْغَوْثُ فَاِذَا رَجُلٌ یُلَا زِمُ رَجُلًا فَقَالَ یَا اَمِیْرَ الْمُوْمِنِیْنَ بِعْتُ مِنْ ھٰذَا ثَوْ بًا بِتِسْعَۃِ دَرَاھِمَ وَشَرَطْتُ عَلَیْہِ اَنْ لَّا یُعْطِیَنِیْ مَغْمُوْرًا وَلَا مَقْطُوْعًا وَکَانَ شَرْ طُھُمْ یَوْ مَئِذٍ فَاَتَیْتُہٗ بِھٰذِہِ الدَّرَاھِمِ لِیُبَدِّ لَھَالِیْ فَاَ بٰی فَلَزِ مْتُہٗ فَلَطَمَنِیْ فَقَالَ اَبْدِ لْہُ فَقَالَ بِیِّنَتَکَ عَلَی اللَّطْمَۃِ فَاَتَا ہُ بِالْبَیِّنَۃِ فَاَقْعَدَہٗ ثُمَّ قَالَ دُوْنَکَ فَاَقِصِّ فَقَالَ اِنِّیْ قَدْ عَفَوْتُ یَا اَمِیْرَ ا لْمُوْ مِنِیْنَ قَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنْ اَحْتَاطَہٗ فِیْ حَقِّکَ ثُمَ ضَرَبَ الرَّجُلَ تِسْعَ دُرَّاتٍ وَقَالَ ھٰذَا حَقُّ السُّلْطَانِ.(تاریخ الطبری سنۃ ۴۰ ھ) یعنی میں نے دیکھا کہ حضرت علی ؓ ہمدان سے باہر مقیم تھے کہ اسی اثناء میں آپ نے دو گروہوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان میں صلح کر ادی لیکن ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ آپ کو کسی شخص کی آواز آئی کہ کوئی خدا کے لئے مدد کو آئے.پس آپ تیزی سے اُس آواز کی طرف دوڑے حتٰی کہ آپ کے جوتوں کی آواز بھی آرہی تھی اور آپ کہتے چلے جاتے تھے کہ ’’مدد آگئی مد د آگئی.‘‘ جب آپ اس جگہ کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے سے لپٹا ہوا ہے.جب اُس نے آپ کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے امیر المومنین! میں نے اس شخص کے پاس ایک کپڑا نو درہم کو بیچا تھا اور شرط یہ تھی کہ کوئی روپیہ مشکوک یا کٹا ہوا نہ ہو.اور اس نے اس کو منظور کر لیا تھا.لیکن آج جو میں اس کو بعض ناقص روپے دینے کے لئے آیا تو اس نے بدلانے سے انکار کر دیا.جب میں پیچھے پڑا تو اس نے مجھے تھپڑ مارا.آپ نے مشتری سے کہا کہ اس کو روپے بدل دے پھر دوسرے شخص سے کہا کہ تھپڑ مارنے کا ثبوت پیش کر.جب اس نے ثبوت دے دیا تو آپ نے مارنے والے کو بٹھا دیا اور اُسے کہا کہ اس سے بدلہ لے.اس نے کہا اے امیر المومنین! میں نے اس کو معاف کر دیا.آپ نے فرمایا تُونے تو اس کو معاف کر دیا مگر میں چاہتا ہوں کہ تیرے حق میں احتیاط سے کام لوں.معلوم ہوتا ہے وہ شخص سادہ تھا اور اپنے نفع نقصان کو نہیں سمجھ سکتا تھا اور پھر اس شخص کو سات کوڑے مارے اور فرمایا اس شخص نے تو تجھے معاف کر دیا تھا مگر یہ سزا حکومت کی طرف سے ہے.غرض اسلام نے مظلوم کو یا بصورت مقتول اس کے ورثاء کو مجرم کا جرم معاف کردینے کی تو اجازت دی ہے مگر ساتھ ہی حکومت کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگر وہ یہ محسوس کرے کہ مظلوم کم فہم ہے یا ظالم کو معاف کردینے سے اس کی دلیری اور شوخی اور بھی بڑھ جائے گی یا مقتول کے ولی اپنے نفع نقصان کو یا پبلک کے نفع نقصان کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے یا خود شریک جرم ہیں تو اس صورت میں باوجود ان کے معاف کر دینے کے خود مجرم کو سزا دے اور اس سے بہتر
Page 154
اور کونسی تجویز دنیا میں امن اور صلح کے قیام کی ہو سکتی ہے.اگر ایک طرف مجرموں کو معاف کر دینے سے خطرات بڑھ جاتے ہیں تو دوسری طرف ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص جرم تو کر لیتا ہے مگر بعد میں وہ خود بھی سخت پشیمان ہوتا ہے اور اس کے رشتہ داروں کی بھی ایسی نازک حالت ہوتی ہے کہ رحم کا تقاضا ہوتا ہے کہ اُسے چھوڑ دیا جائے اور خود جن لوگوں کے خلاف وہ جرم ہوتا ہے وہ بھی یا اُن کے ولی بھی چاہتے ہیں کہ اُس سے درگذر کریں ایسی صورت میں دونوں کے تقاضا کو پورا کرنے کے لئے موجودہ تمدن نے کوئی علاج نہیں رکھا.صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے تیرہ سو سال پہلے سے ساتویں صدی کے تاریک تمدن میں ایسے اعلیٰ درجہ کے تمدن کی بنیاد رکھی جس کی نظیر بیسویں صدی کا دانا مدبّر بھی پیش نہیں کر سکتا.لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے عفو سے کام لینا حاکم کا کام نہیں بلکہ مقتول کے اولیاء اور ورثاء کا کام ہے.ہاں اگر حاکم مجاز دیکھے کہ عفواپنے اندر مضّرات کے بعض پہلو رکھتا ہے تو وہ معافی کو کالعدم بھی قرار دے سکتا ہے.جیسا کہ حضرت علیؓ کے واقعہ سے ثابت کیا جا چکا ہے لیکن اگر وہ شخص جس کا حق ہے قصاص لے معاف نہ کرنا چاہے تو حکام کا فرض ہے کہ وہ لازماً قصاص لیں.مِنْ اَخِیْہِ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض اوقات دشمنی اور عداوت اور بُغض سے قتل نہیں ہوتا بلکہ کسی وقتی جوش اور اشتعال کے نتیجہ میں بھی قتل ہو جاتا ہے اس لئے اَخِیْ کہہ کر قاتل کے لئے رحم کی تحریک کر دی کہ آخر وہ تمہارا بھائی ہے.اگر اُس سے نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی ہے تو تم جانے دو اور اُسے معاف کر دو.اِدھر قاتل کو بھی شرمندہ کیا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے.شَیْ ءٌ اس جگہ نکرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں نکرہ تعظیم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور تحقیر کے لئے بھی.پس فَمَنْ عُفِیَ لَہٗ مِنْ اَخِیْہِ شَیْءٌ سے مراد کُلّی معافی بھی ہو سکتی ہے اور جزوی بھی یعنی قتل نہ کرنا اور دیّت لے لینا یا دیّت میں بھی کمی کر دینا جائز ہے اور قتل نہ کرنا اور دیت بھی نہ لینا جائز ہے.دونوں صورتوں میں سے جو بھی کوئی چاہے اختیار کر سکتا ہے اور اگر بعض ورثاء معاف کر دیں اور بعض نہ کریں تو قاتل کو قتل کی سزا نہیں دی جائےگی جیسے مقتول کے دو بیٹے ہوں ان میں سے ایک معاف کر دے اور دوسرا نہ کرے تو قاتل قتل نہیں ہو گا لیکن اگر حاکم سمجھے کہ چونکہ وارث ہی شرارت سے مروانے والے ہیں.اس لیے وہ معاف کرتے ہیں تو حاکم معاف نہیں کرے گا.بلکہ انہیں سزا دے گا.اور وارثوں کی شرارت ثابت ہو جانے کی وجہ سے ان کی وراثت کا حق بھی زائل ہوجائےگا.فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ میں یہ بتایا کہ دیّت لینے والے کو چاہیے کہ مناسب رنگ میں
Page 155
دیّت وصول کرے.یعنی اگر قاتل یکدم ادا نہیں کر سکتا تو وصول کرنے میں سختی نہ کرے بلکہ اُسے کچھ مہلت دے دے او ر دیّت دینے والے کو چاہیے کہ وہ ادا کرنے میں سُستی یا شرارت نہ کرے بلکہ تکلیف اٹھا کر بھی دیت ادا کر دے اور کسی ناواجب تاخیر یا شرارت سے کام نہ لے.ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ.فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے آسانی پیدا کر دی گئی ہے اور اس ذریعہ سے اس نے تمہارے لئے اپنی رحمت کا سامان مہیّاکیا ہے.تمہیں چاہیے کہ اسے مدِّنظر رکھو اور خدا تعالیٰ کے اس احسان کی قدر کرو.فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فرماتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرےگا اور اِعْتَدٰی سے کام لےگا تو اس کے لئے دردناک عذاب مقدّر ہے.یعنی اگر مقتول کے ورثاء دیّت بھی لے لیں اور موقعہ پا کر دوسرے کو بھی قتل کر دیں تو وہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہوںگے بلکہ انہیں لازماً سزا دی جائے گی.یعنی حکومت دوسرے فریق کو انہیں معاف کرنے کی اجازت بھی نہیں دےگی تاکہ اس قسم کی وحشیانہ حرکات قومی اخلاق کو نہ بگاڑیں اور لوگوں کے اندر قانون کا احترام قائم ہو.وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۰۰۱۸۰ اور اے عقلمندو! تمہارے لئے (اس) بدلہ لینے میں زندگی (کا سامان) ہے (اور یہ حکم اس لئے ہے) تاکہ تم بچ جاؤ.حلّ لُغات.اَلْاَلْبَابُ جمع ہے.اس کا مفرد لُبٌّہے اور لُبٌّ کے معنے مغز کے ہیں.لیکن مراد عقل ہے.تفسیر.فرماتا ہے.اے عقلمندو! قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والا تو مر گیا اب اگر اس کے قاتل کو قتل کر دیا جائےگا تو مقتول تو زندہ نہیں ہو سکتا پھر قصاص میں حیات کس طرح ہوئی؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر قاتل کو قتل نہ کیا جائے تو بالکل ممکن ہے کہ کل وہ کسی دوسرے کو قتل کر دے اور پرسوں کسی اور کو مار ڈالے.اس لئے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے.یعنی اگر قاتل سے قصاص نہ لیا جائےگا تو وہ تم میں سے کسی اور کی زندگی کا خاتمہ کر دے گا لیکن اگر قاتل کو موت کی سزا دی جائے تو آئندہ قتل کے جرم کم ہو جائیںگے اور اس طرح کئی لوگوں کی جانیں بچ جائیںگی.پھر اس رنگ میں بھی قصاص حیات کا موجب ہے کہ جب قاتل کو سزا مل جاتی ہے تو رشتہ داروں کے دلوں میں
Page 156
سے بُغض اور کینہ نکل جاتا ہے اور مقتول کی عزت قائم ہو جاتی ہے.اگر قاتل کو سزا نہ ملے تو رشتہ داروں کے دل میں بغض اور کینہ رہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آدمی کو قتل کر کے اس کی ذلّت کی گئی ہے.پس قصاص مقتول کی عزّت قائم کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے لیکن اس کے علاوہ میرے نزدیک اس آیت میں موجودہ زمانہ کے متعلق ایک پیشگوئی بھی پائی جاتی ہے.عرب تو قصاص کے بڑی سختی سے پابند تھے.یہاں تک کہ اگر باپ مارا جائے تو وہ پوتے سے بھی اس کابدلہ لے لیتے تھے.پس یہ ہدایت صرف ان کو نہیں ہو سکتی بلکہ درحقیقت یہ آئندہ زمانہ کے لئے پیشگوئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ قصاص کو اُڑانے کی تلقین کی جائےگی اُس وقت تم مضبوطی سے اس تعلیم پر قائم رہنا جیسے آج کل بعض یوروپین ممالک میں اس قسم کی تحریکات وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی ہیں کہ موت کی سزا منسوخ ہونی چاہیے.خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے عقلمندو! ان تحریکات کو کبھی قبول نہ کرنا ورنہ اس کے بہت سے مفاسد ظاہر ہوںگے.اور تمہاری جانوں کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی.آخر میںلَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے یہ حکم اسی لئے دیا ہے کہ تم قتل سے بچو اور اس زندگی کو پائو جو قصاص کے نتیجہ میں حاصل ہوتی ہے اگر تم قصاص کو چھوڑ دو گے تو نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہارا تمدن درہم برہم ہو جائےگا.پس تم اس بات سے بچو کہ تمہارا تمدن ٹوٹ جائے اور تمہار ا نظام درہم برہم ہو جائے او ر تمہاری جانوں اور مالوں کی کوئی قیمت باقی نہ رہے.پھر اس کے علاوہ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ کے ایک اور معنے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھائے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ان الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی کی تمہیں اس لئے ضرورت ہے کہ تم اور تقویٰ حاصل کر لو.گویا بتایا کہ بے فائدہ جان گنوانا اس لئے قابلِ احتراز ہے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اس میں رہنے سے آخرت کا توشہ انسان جمع کر لیتا ہے.پس اس کی حفاظت بھی ضروری ہے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو.غرض ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ مومن باوجود آخرت پر ایمان رکھنے کے زندگی کی کیوں قدر کرتا ہے.كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا١ۖۚ جب تم میں سے کسی پر موت (کا وقت) آجائے تو تم پر بشرطیکہ وہ (یعنی مرنے والا) بہت سا مال چھوڑ ے.ا۟لْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ١ۚ حَقًّا والدین اور قریبی رشتہ داروں کو (امر) معروف کی وصیت کر جانا فرض کیا گیا ہے.
Page 157
عَلَى الْمُتَّقِيْنَؕ۰۰۱۸۱ (یہ بات ) متقیوں پر واجب ہے.حل لغات.خَیْرًا مفردات میں لکھا ہے وَقَوْلُہٗ تَعَالٰی اِنْ تَرَکَ خَیْرًا اَیْ مَالًا وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَایُقَالُ لِلْمَالِ خَیْرٌ حَتّٰی یَکُوْنَ کَثِیْرًا وَمِنْ مَکَانٍ طَیِّبٍ.یعنی اس آیت میں خَیْراً سے مراد مال ہے اور بعض علماء کے نزدیک مال کو خَیْرٌ اس وقت کہیں گے جب وہ زیادہ ہو اور نیک ذرائع سے کمایا ہو ا ہو.(مفردات) تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے متعلق مرنے والے کو جو وصیت کرنے کا حکم دیا ہے اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی وصیت ہے جس کی تعلیم دی گئی ہے.جبکہ شریعت نے خود احکام وراثت کو سورۃ نساء میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے اور ان کے نزول کے بعد رشتہ داروں کے نام وصیت کرنا بے معنی بن جاتا ہے؟ سو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وصیت کے احکام چونکہ دوسری آیات میں نازل ہو چکے ہیں اس لئے یہ آیت منسوخ ہے اب اِس پر کسی عمل کی ضرورت نہیں.مگر ہمارے نزدیک قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں.قرآنی آیات کی منسوخی کا عقیدہ محض قلّتِ تدبّر کی بنا پر ظہور میں آیا ہے.جب مسلمانوں کو کسی آیت کا مفہوم پوری طرح سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ منسوخ ہے اور اس طرح کئی کئی سو آیات تک انہوں نے منسوخ قرار دے دیں.اگر وہ سمجھتے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف قابلِ عمل ہے تو وہ ہر آیت پر غور کرتے.اور اگر اسے حل کرنے سے قاصر رہتے تو خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے اوراس سے دعائیں کرتے کہ وہ اُن کی مدد کرے اور اپنے کلام کی حقیقت سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے اور اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اُن کی رہنمائی کے سامان پیدا فرما دیتا اور انہیں مشکل آیات کا حل نظر آجاتا مگر انہوں نے بدقسمتی سے یہ آسان رستہ اختیار کر لیا کہ جس آیت کا مطلب سمجھ میں نہ آیا اُسے منسوخ قرار دے دیا.یہی طریق انہوںنے یہاںبھی اختیار کر لیا ہے مگر اس آیت کے جو معنے ہم کرتے ہیں.اگر اس کو مدِّنظر رکھا جائے تو یہ حکم بڑا ہی پُر حکمت نظر آتا ہے اور اسے منسوخ قرار دینے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی.درحقیقت یہاں وصیت کا لفظ صرف عام تاکید کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس کا ایک بڑاثبوت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے والدین اور اقربین کے متعلق تو وصیت کرنےکا حکم دیا ہے مگر اولاد کو ترک کر دیا ہے.حالانکہ قلبی تعلق کے لحاظ سے اولاد کا ذکر بھی ضرور ہونا چاہیے تھا
Page 158
یہ بات بتاتی ہے کہ یہاں مال کی تقسیم کا مسئلہ بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ ایک عام تاکید کی جا رہی ہے اور اولاد کی بجائے والدین اور اقربین کا ذکر ا س لئے کیا گیا ہے کہ اس آیت کا سیاق وسباق بتا رہا ہے کہ یہ حکم جنگ اور اس کے مشابہ دوسرے حالات کے متعلق ہے.چنانچہ اس سے چند آیات پہلے وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ میں لڑائی کا ذکر آچکا ہے.اسی طرح آگے چل کر وَقَا تِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَکُمْ میں پھر جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور چونکہ جنگ میں بالعموم نوجوان شامل ہوتے ہیں.جن کے ہاں یا تو اولاد ہوتی ہی نہیں یا چھوٹی عمر کی ہوتی ہے.اس لئے والدین اور اقربین کے حق میں وصیت کرنےکا حکم دیا اور اولاد کا ذکر چھوڑدیا اور یہ ہدایت فرمائی کہ جب کسی شخص کی موت کا وقت قریب آجائے یا وہ کسی ایسے خطرناک مقام کی طرف جانے لگے جہاں جانے کا نتیجہ عام حالات میں موت ہوا کرتا ہے.اور پھر اُس کے پاس مال کثیر بھی ہو تو اُسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے کہ اُس کی جائیداد احکام الٰہیّہ کے مطابق تقسیم کی جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو.اور یہ تاکید بجائے اس کے کہ کسی اور کو کی جائے اپنے رشتہ داروں کو کرے.اور اگر مال کا کوئی حصہ صدقہ کرنا ہو تو اس کا بھی اظہار کر دے.میں سمجھتا ہوں اگر مسلمان اِس تعلیم پر عمل کرتے تو وہ رواج جو شرعی تقسیم وراثت کے خلاف اُن میں جاری رہا کبھی جاری نہ ہوتا.جس ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہو وہاں تو کسی رواج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.لیکن ایسے ممالک جہاں رواج کا سوال پیدا ہو وہاں اس امر کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں یہ وصیت کر جائے کہ اُن میں معروف کے مطابق جائیداد تقسیم کی جائے ورنہ اُس کا مال رواجی مستحقوں کو مل جائےگا اوراصل مستحقین محروم رہ جائیں گے.رہایہ سوال کہ معروف کیا ہے ؟سوایک تو احکام وراثت معروف ہیں اُن پر عمل کرنے کی تاکید ہونی چاہیے.دوسرے بعض حقوق ایسے ہیںجو احکامِ وراثت سے باہر ہیں.اور جن کو قاعدہ میں تو بیان نہیں کیا گیا مگر مذہبی اور اخلاقی طور پر انہیں پسند کیا گیا ہے اوراُن کے لئے شریعت نے 1/3تک وصیت کردینے کا دروازہ کھلا رکھا ہے.مثلاً اگر وہ چاہے تو کچھ روپیہ غربا ء کی بہبودی کےلئے وقف کر دے اور اس کی اپنے رشتہ داروں کو تاکید کر جائے.الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ورثا ء کا فرہوں تو اُن کےلئے حُسنِ سلوک کی وصیت کر جائے.کیونکہ ایسی صورت میں وصیت کے بغیر کافروالدین یا دوسرے قریبی رشتہ داروں کو کچھ نہیں مل سکتا.اگر وہ دیکھے کہ انہیں کچھ مال دے دینے سے فائدہ ہوگا تو اُن کے متعلق تاکید کر دے کہ فلاں فلاں شخص کو میرے مال میں سے اس قدر حصّہ ضرور دے دیا جائے اور اگر دیکھے کہ وہ اس روپیہ کو اسلام کے خلاف خرچ کریں
Page 159
گے تو نہ دے.کافر والدین یا اقربین کےلئے ورثہ نہیں رکھا گیا.ہاں وصیت کی گنجائش رکھی گئی ہے تاکہ اگر وہ اسلام کے خلاف اپنے مال کو استعمال کرنے والے ہوں تو انہیں مال نہ پہنچ سکے اور اگر جائز طور پر مدد کے مستحق ہوں تو اُن کی مدد کی جا سکے.اِس آیت کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اپنے پوتوں اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کےلئے بھی کچھ وصیت کر جائے تاکہ اُن کی مدد ہو جائے.اور شریعت کے کسی حکم کی بھی خلاف ورزی نہ ہو.کیونکہ اسلامی قانون کی رُو سے اگر دادا کی زندگی میں اس کا بیٹا فوت ہو جائے تو پوتوں اور پوتیوں کو وراثت سے حصہ نہیں ملتا.پس ایسی صورت میں اگر وہ اپنی جائیداد کے 1/3 حصہ میں سے اپنے پوتوں ،پوتیوں یا بھائیوں کے بیٹوں کو کچھ روپیہ دینا چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے.(۴) جن ممالک میں اپنے اپنے قانون رائج ہیں وہاں دو صورتیں ہیں.بعض تو ایسی جگہیں ہیں جہاں مرنے کے وقت کی وصیت کو ہی معتبر سمجھا جاتا ہے.جیسے روس کا ملک ہے اور بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مرنے والے کی وصیت پر عمل نہیں ہوتا بلکہ حکومت نے جو قانون مقرر کیا ہوا ہو اس کے مطابق ورثہ تقسیم ہوتا ہے.اگر ایسے ممالک ہوں جہاں مرنے والے کی وصیت تسلیم کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہو گا کہ جن ورثاء کو رواج کے مطابق ورثہ نہیں مل سکتا انہیں وصیت کی وجہ سے شریعت کے مطابق حصہ مل جائےگا اور اسلامی تعلیم اُن ممالک میں بھی زندہ ہو جائےگی جن میں گو اسلامی حکومت نہیں مگر وہ مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا ضروری سمجھتے ہیں.اور جہاں اسلامی قانون کے مطابق ورثہ تقسیم نہ ہو سکتا ہو وہاں خواہ جائز ورثاء کو ورثہ نہ مل سکے پھر بھی اس کے نتیجہ میں مسلمان اس گناہ سے بچ جائیں گے جو اس حکم کی خلاف ورزی کے ساتھ وابستہ ہے اور صرف وصیت تبدیل کرنے والے گنہگار قرار پائیں گے.مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وصیت کا ہر گز یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی وارث کو جس کا شریعت نے حصّہ مقرر کر دیا ہے اس کے حق سے زیادہ دے دے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے.چنانچہ حدیث میں آتا ہے اِنَّ اللّٰہَ اَعْطیٰ کُلَّ ذِیْ حَقٍّ حَقَّہٗ وَلَا وَصِیَّۃَ لِوَارِثٍ (ترمذی ابواب الوصایا باب ما جاء لا وصیۃ لوارث) اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق مقرر کر دیا ہے.اس لئے کسی وارث کےلئے جس کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا ہے.وصیت نہیں ہو سکتی.پس یہ آیت نہ منسوخ ہے نہ بلا ضرورت.بہت دفعہ مرنے کے بعد ورثا ء میں تقسیم مال پر جھگڑا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ غیر رشتہ دار بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اتنا روپیہ دینے کا اس نے وعدہ کیا تھا.اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ مرنےوالے کو وصیت کر دینی چاہیے تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہواور یہ سوال نہ اُٹھے کہ
Page 161
اشارہ ہے اور وہ حکم وراثت کا ہی ہے ورنہ اس کا کیا مطلب کہ بدلنے کا گناہ بدلنے والوں پر ہو گا وصیت کرنے والے پر نہیں ہوگا کیونکہ اگر اس وصیت کی تفصیلات شرعی نہیں تو بدلنے والے کو گناہ کیوں ہو ؟ اُس کے گناہ گار ہونے کاسوال تبھی ہو سکتا ہے جبکہ کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو.اور وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ مرنے والا تو یہ وصیت کر جائے کہ میری جائیداد احکام اسلام کے مطابق تقسیم کی جائے لیکن وارث اس کی وصیت پر عمل نہ کریں.ایسی صورت میں وصیت کرنے والا تو گناہ سے بچ جائے گا لیکن وصیت تبدیل کرنے والے وارث گناہ گار قرار پائیں گے.فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے طرف داری یا گناہ (کے سر زد ہونے )کا خوف کرے اور ان کے درمیان فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌؒ۰۰۱۸۳ صلح کرا دے.تو اس پر کوئی گناہ نہیں.اللہ یقیناً بہت بخشنے والا (اور )بار بار رحم کر نے والا ہے.حلّ لُغات.جَنَفًا جَنَفَ کا مصدر ہے اور جَنَفَ فِی الْوَصِیَّۃِکے معنے ہیں مَالَ وَجَارَ یعنی اُس نے وصیت کرتے ہوئے نا انصافی کی اور عدل کے راستہ سے ہٹ گیا.(اقرب) تفسیر.اب بتایا کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ موصی کی وصیّت میں کوئی نقص ہے اور خوف ہو کہ اس سے فتنہ پیدا ہو گا تو وہ ورثاء کو جمع کر کے اگر ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں.یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جب اس نے شریعت کے مطابق اپنی جائیداد تقسیم کرنے کی ہدایت کی ہے تو ورثاء کو نقصان پہنچنے کا احتمال کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شریعت پر عمل کرنے کے باوجود وصیّت کرنے کی صورت میں بعض نقصانات کا بھی احتمال ہو سکتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص 1/3حصّہ کی وصیّت کردے اور باقی وارث اتنے ہوں کہ بقیہ مال میں سے ان کو بہت کم حصہ ملتا ہو تو ایسی صورت میں اگروصیّت کرنے والے اور ان رشتہ داروں کے درمیان جن کو نقصان پہنچنے یا جن کے نظر انداز کئے جانے کا امکان ہو صلح کر ادی جائے یا وہ شخص جن کے حق میں وصیّت ہے ان کو باہمی سمجھوتے سے اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ باوجود وصیت کے وہ ایک دوسرے کو اس کا حق ادا کردیںگے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں.اسے چاہیے کہ وصیت کرنے والے اور اس کے محبوب یا مبغوض ورثاء میں صلح کرا دے تاکہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو.
Page 162
دوسری صورت یہ ہے کہ وصیت کرتے وقت اگر وصیت کرنے والا کسی فریق کو نقصان پہنچا رہا ہو اور جسے وصیت لکھوائی جا رہی ہو وہ سمجھتا ہو کہ بعض ورثاء سے اُس کی اَنْ بنْ ہے اور اس ناراضگی کی وجہ سے یہ ایسی وصیت کر رہا ہے تو اُسے سمجھا دے.اور مرنے والے اور اس کے وارثوں میں صلح کرا دے تو یہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں اور اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے.فَلَا اِثْمَ عَلَیْہِ سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ اس قسم کی اصلاح اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پسندیدہ کام نہیں بلکہ صرف ایک منفی نیکی ہے جس میں انسان کے گنہگار ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا.کیونکہ یہ الفاظ اس فعل کو صرف ایک منفی نیکی قرار دینے کے لئے استعمال نہیں کئے گئے بلکہ اس لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے فرمایا تھا کہ فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ یعنی جو شخص وصیت کو اس کے سننے کے بعد بدل دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گناہ گار ہو گا.پس چونکہ اس سے پہلے وصیت میں تبدیلی کرنا اللہ تعالیٰ نے گناہ کا موجب قرار دیا تھا اس لئے لازماً یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بعض محتاط طبیعتیں کہیں اس طرف مائل نہ ہو جائیں کہ وصیت میں غلطی واقع ہونے کے باوجود پھر بھی اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب نہ ہو.پس اس قسم کے خدشات کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے زیر تفسیر آیت میں بتا دیا کہ اگرواقعہ میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو تو اس کو دُور کردینا ہرگزکوئی گناہ کی بات نہیں بلکہ ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بنا دےگی.چنانچہ آخر میںاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو وصیت کرنے والے کو تسلّی دی کہ اگر وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دے گا اوردوسری طرف رَحِیْمٌ فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مداخلت کر کے وصیت کے نقائص کو دُور کروانے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرےگا اور اُسے اپنے فضلوں کا مورد بنائےگا.پس غَفُوْرٌ کالفظ ان وصیت کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے جو اپنی غلطی کی اصلاح کرلیں.اور رَحِیْمٌ کا لفظ ان لوگوں کے موردِ انعام ہونے پر دلالت کرتا ہے جو وصیت کی کسی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں.
Page 163
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تم پر (بھی )روزوں کا رکھنا (اسی طرح) فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ۰۰۱۸۴ گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں.تاکہ تم (روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے) بچو.حلّ لُغات.تَتَّقُوْنَ اِتَّقٰی سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے.اور تَقْوٰی کے معنے ہیں جَعْلُ النَّفْسِ فِیْ وَ قَایَۃٍ مِـمَّا یُخَافُ...وَفِیْ تَعَارُفِ الشَّرْعِ حِفْظُ النَّفْسِ عَمَّا یُؤْثِمُ(مفردات) یعنی اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے ایک ڈھال کے پیچھے محفوظ کر لیا جن سے خوف محسوس کیا جاتا ہے.اور شرعی نقطہ نگاہ سے تقْوٰی سے مراد گناہوں سے بچنا ہے.اِتَّقٰی وَقٰی سے بابِ اِفتعال کا فعل ماضی ہے وَقٰی کے معنے ہیں بچایا ، حفاظت کی.اور اِ تَّقـٰی کے معنے ہیں.بچا.اپنی حفاظت کی (اقرب) مگر اس لفظ کا استعمال دینی کتب کے محاورہ میں معصیت اور بُری اشیاء سے بچنے کے ہیں اور خالی ڈر کے معنو ںمیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا.وَقَایَۃٌ کے معنی ڈھال یا اس ذریعہ کے ہیں جس سے انسان اپنے بچائو کا سامان کرتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اتقاء جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو انہی معنوں میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نجات کے لئے بطور ڈھال بنا لیا.قرآن کریم میں تقویٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں حضرت ابوہریرہؓ سے کسی نے پوچھا تو انہوںنے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزرو تو کیا کرتے ہو ؟ اس نے کہا یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں یا آگے نکل جاتا ہوں.انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے ایک شاعر (اِبنُ المُعتز) نے ان معنوں کو لطیف اشعار میں نظم کر دیا ہے وہ کہتے ہیں.خَلِّ الذُّنُوْبَ صَغِیْرَھَا وَکَبِیْرَھَا ذَاکَ التُّقٰی وَاصْنَعْ کَمَاشٍ فَـوْقَ اَرْ ضِ الشَّوْکِ یَحْذَرُ مَایَرَیٰ لَا تَحْقِرَنَّ صَغِیْرَۃً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصٰی (ابن کثیر)
Page 164
یعنی گناہوں کو چھوڑ دے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہ تقویٰ ہے اور تو اُس طریق کو اختیار کر جو کانٹوں والی زمین پر چلنے والا اختیار کرتا ہے یعنی وہ کانٹوں سے خوب بچتا ہے اور تو چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ کیونکہ پہاڑ کنکروں سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں.تفسیر.فرماتا ہے.اے مومنو!تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزے رکھنے اسی طرح فرض کئے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر روزے رکھنے فرض کئے گئے تھے.دنیا میں بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو منفرد ہوتی ہیں.اکیلے انسان پر آتی ہیں اور وہ ان سے گھبراتا ہے.شکوہ کرتا ہے کہ میں ان تکالیف کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا.لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سارے لوگ شریک ہوتے ہیں.ان تکالیف پر جب کوئی انسان گھبراتا یا شکوہ کا اظہار کرتا ہے تو لوگ اُسے یہ کہہ کر تسلّی دیا کرتے ہیں کہ میاں یہ دن سب پر آتے ہیں اور کوئی شخص یہ امید نہیں کر سکتا کہ وہ ان تکلیفوں سے بچ جائے.مثلاً موت ہے موت ہر انسان پر آتی ہے.دنیا میں کوئی احمق سے احمق انسان بھی ایسا نہیں مل سکتا جو کہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ پر موت نہ آئے.موت اس پر ضرور آئے گی چاہے جلدی آجائے یا دیر میں.پس كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ کہہ کر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ روزے ایسی نیکی ، ثواب اور قربانی ہیں جن میں سارے ہی ادیان شریک ہیں اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا ہے.پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ جس کے حصول کے لئے ساری قومیں کوشش کرتی رہی ہیں تم اس سے بچنے کی کوشش کرو! اگر یہ کوئی نیا حکم ہوتا اگر روزے صرف تم پرہی فرض ہوتے تو تم دوسرے لوگوں سے کہہ سکتے تھے کہ تم اسے کیا جانو! تم نے تو اس کا مزہ ہی نہیںچکھا.لیکن وہ لوگ جو اس دروازہ میں سے گذر چکے ہیں.اور جو اس بوجھ کو اٹھا چکے ہیں انہیں تم کیا جواب دو گے؟ لازماً مسلمانوں پر حجت اُنہی احکام میں ہوسکتی ہے جو پہلی قوموں کو بھی دیئے گئے اور انہوں نے ان احکام کو پورا کیا.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اے مسلمانو! تم ہوشیار ہو جائو ہم تم پر روزے فرض کرتے ہیں.اور ساتھ ہی تمہیں بتا دیتے ہیں کہ روزے پہلی قوموں پر بھی فرض کئے گئے تھے.اور انہوں نے اس حکم کو اپنی طاقت کے مطابق پورا کیا تھا اگر تم اس حکم کو پورا کرنے میں سستی دکھائو گے تو وہ قومیں تم پر اعتراض کریں گی اور کہیں گی کہ ہمیں بھی خدا تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا تھا اور ہم نے اُسے پورا کیا اب تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں تو تم اس حکم کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے.غرض مسلمانوں کی غیرت اور ہمت بڑھانے کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کئے گئے بلکہ پہلی قوموں پر بھی فرض کئے گئے تھے.اور ان قوموں نے اپنی طاقت
Page 165
کے مطابق اس حکم کو پورا کیا تھا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ روزوں کی شکل میں اختلاف تھا اور وہ اختلاف آج تک نظر آتا ہے.کہیں اس قسم کے روزے ہوا کرتے تھے جنہیں وصال کہتے ہیں کہ درمیان میں سحری نہ کھانا.اس قسم کے روزوں میں صرف شام کے وقت روزہ کشائی کی جاتی اور دوسری سحری نہ کھا کر متواتر آٹھ پہر روزہ رکھا جاتا.کہیں ایسے روزے ہوتے کہ روزہ کشائی بھی نہ ہوتی اور تین تین چارچار پانچ پانچ دن متواتر روزہ رکھا جاتا.ایسے روزے بھی پائے جاتے ہیں جن میں لوگوں کو ہلکی غذا کھانے کی اجازت دی گئی ہے مگر ٹھوس غذائوں سے منع کیا گیا ہے جیسے ہندوئوں یا عیسائیوں میں روزے ہوتے ہیں.ہندوئوں کے روزوں کے متعلق تو عام طور پر مشہور ہے کہ ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھانی.اس کے علاوہ اگر وہ کئی سیر آم ، کیلے، اورنارنگیاں وغیرہ کھا جائیں تو ان کے روزہ میں فرق نہیں آتا.روٹی اور سالن کو چھوڑ کر باقی جو چیزچاہیں کھا لیں.پھر اس سے بھی آسان روزے رومن کیتھولک عیسائیوں میں پائے جاتے ہیں.آخر انہوں نے بھی کسی مذہبی روایت کی بنا پر ہی یہ روزے رکھنے شروع کئے ہوںگے یا کسی حواری سے کوئی بات پہنچی ہو گی.اُن کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت نہیں کھانا.اگر وہ آلو اُبال کر یا کدو کا بھرتہ بنا کر اس کے ساتھ روٹی کھالیں تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا البتہ اگر گوشت کی بوٹی ان کے معدہ میں چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے(انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Fasting )پس روزوں کے متعلق بھی مختلف اقوام میں اختلاف پائے جاتے ہیں.اور اپنے اپنے زمانہ میں ان احکام میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی پوشیدہ ہوںگی.مثلاً جو قومیں کثرت سے گوشت کھانے والی ہوں وہ ان اخلاق سے رفتہ رفتہ محروم ہو جاتی ہیں جو سبزی کے استعمال کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں.ایسے لوگوں کی اخلاقی اصلاح کے لئے اور انہیں یہ بتانے کے لئے کہ سبزی بھی غذا میں ضروری ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا ہو کہ ہفتہ میں کم از کم ایک دن تم پر ایسا آنا چاہیے جب تم گوشت نہ کھائو.تو یہ نہایت پُر حکمت روزہ ہو جاتا ہے.اس کے مقابلہ میں اسلام نے ہماری غذا کے متعلق یہ ایک عام حکم دے دیا ہے کہ گوشت بھی کھائو اور سبزیاں بھی کھائو.آگ پر پکی ہوئی چیزیں بھی استعمال کرو اور جنہیں آگ نے نہ چُھؤا ہو وہ بھی استعمال کر لو.غرض ہماری غذا میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی احتیاطیں جمع کر دی ہیں.لیکن پہلی قوموں کے لئے ممکن ہے اس قسم کی احتیاطیں ناقابلِ برداشت پابندیاں ہوں اور ان کے اخلاق کی اصلاح کے لئے اس قسم کے روزے تجویز کئے گئے ہوں.مثلاً وہ قومیں جو جنگی ہوتی ہیں اور جن کا شکار پر گذارہ
Page 166
ہوتاہے وہ ایک عرصہ تک گوشت کھانے کی وجہ سے ایسے اخلاق سے عاری ہو جاتی ہیں جو سبزی کھانے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں.ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دےدیا گیا ہو کہ وہ ہفتہ میں ایک دن گوشت کھانا چھوڑ دیں تو یقیناً یہ روزہ ان کے لئے بہت مفید تھا.پس پہلی قوموں میں روزے تو تھے مگر شکل وہ نہ تھی جو اسلام میں ہے پس كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ میں جو مشابہت پہلے لوگوں کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ کمیّت اور کیفیّت کے لحاظ سے نہیں بلکہ صرف فرضیت کے لحاظ سے ہے یعنی کَمَا کُتِبَ سے یہ مراد نہیں کہ وہ ویسے ہی روزے رکھتے تھے جیسے مسلمان رکھتے ہیں.یا اُتنے ہی روزے رکھتے تھے جتنے مسلمان رکھتے تھے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر بھی روزے فرض تھے اور تم پر بھی فرض کئے گئے ہیں گویا صرف فرضیت میں مشابہت ہے نہ کہ تفصیلات میں.چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں ـ’’روزہ‘‘ کے ماتحت لکھا ہے کہ.IT WOULD BE DIFFICULT TO NAME ANY RELIGIOUS SYSTEM OF ANY DESCRIPTION IN WHICH IT IS WHOLLY UNRECOGNISED.یعنی دنیا کا کوئی باقاعدہ مذہب ایسا نہیں جس میں روزہ کا حکم نہ ملتا ہو.بلکہ ہر مذہب میں روزوں کا حکم موجود ہے.چنانچہ اس بارہ میں سب سے پہلے ہم یہودی مذہب کو دیکھتے ہیں.تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو انہوں نے چالیس دن رات کا روزہ رکھا اور ان ایام میں انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا.چنانچہ لکھا ہے.’’سو وہ (یعنی موسیٰ) چالیس دن اور چالیس رات وہیں خدا وند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا.‘‘ (خروج باب۳۴ آیت۲۸) اسی طرح احبار باب۱۶ آیت۲۹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو ایک روزہ رکھنا یہود کے لئے ضروری قرار دیا گیا تھا.چنانچہ بنی اسرائیل ہمیشہ یہ روزے رکھتے رہے اور انبیاء بنی اسرائیل بھی اس کی تاکید کرتے رہے.زبور میں حضرت دائود ؑ فرماتے ہیں.’’میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑھا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دُکھ دیا.‘‘ (زبور باب ۳۵ آیت۱۳) یسعیاہ نبی فرماتے ہیں.’’ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو.پس اب تم
Page 167
اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالمِ بالا پر سُنی جائے.‘‘ (یسعیاہ باب۵۸ آیت۴) دانی ایل فرماتے ہیں.’’ میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اُس کا طالب ہوا.‘‘ (دانی ایل باب۹ آیت۳) یو ایل نبی فرماتے ہیں.’’خداوند کا روزِ عظیم نہایت خوفناک ہے.کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ وزاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لائو اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ رحیم و مہربان قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے.‘‘ (یو ایل باب ۲ آیت۱۱ تا۱۳) یہودیت کے بعد عیسائیت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی روزوں کا ثبوت ملتا ہے.چنانچہ حضرت مسیح ؑ کے متعلق انجیل بتاتی ہے کہ انہوں نے چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھا.متی میں لکھا ہے.’’ اور چالیس دن اور چالیس رات فاقہ کر کے آخر کو اُسے بھوک لگی‘‘ (متی باب ۴ آیت ۲) اسی طرح حضرت مسیح ؑ نے اپنے حواریوں کو ہدایت دی کہ.’’جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اُداس نہ بنائو کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں.میں تم سےسچ سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے.بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے.اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دےگا.‘‘ (متی باب۶ آیت۱۶ تا۱۸) اِسی طرح ایک دفعہ جب حواری ایک بد روح کو نہ نکال سکے تو ’’ اُس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے تو اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا اور روزہ کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی.‘‘ (مرقس باب۹ آیت۲۸،۲۹)
Page 168
بد رُوح نکالنا حواریوں کی ایک اصطلاح تھی.وہ بیماریوں اور مختلف قسم کی خرابیوں کو دیو کہا کرتے تھے اور حضرت مسیح ؑ ناصری کے پاس آکر درخواست کیا کرتے تھے کہ یہ دیو نکال دیں.ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بیماریاں یا خاص قسم کی دماغی خرابیاں دُور کر دی جائیں.اس قسم کے بعض بیمار تھے جن کا حضرت مسیح ؑ ناصری نے علاج کیا اور وہ اچھے ہو گئے.اور جب ایک موقعہ پر حواری ایک بد رُوح کو نہ نکال سکے تو آپ نے فرمایا.کہ یہ دیو روزوں اور دعائوں کے بغیر نہیں نکلتے.یعنی کمالاتِ رُوحانیہ کا حصول روزوں اور دُعائوں کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے.لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہی مسیح ؑ ناصری جنہوں نے یہ کہا تھاکہ بڑی بڑی بیماریاں روزوں اور دعائوں کے بغیر نہیں نکل سکتیں.انہی کی اُمّت آج روزوں سے اتنی بے خبر ہے اور وہ اتنا کھاتے ہیں کہ شاید ایشیائی ہفتہ بھرمیںبھی اتنا نہیں کھاتے جتنا وہ ایک دن میں کھا جاتے ہیں.پس انہوں نے روزہ کیا رکھنا ہے وہ تو روزوں کے قریب بھی نہیں جاتے.سال بھر میں صرف تین دن ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن ہندوئوں کی طرح جیسے وہ روزہ میں صرف چولھے کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے.مثلاً وہ پھلکا نہیں کھائیں گے لیکن دودھ دو دو سیر پی جائیں گے.عیسائی بھی صرف چند چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں باقی سب کچھ کھاتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ روزے ہو گئے.حالانکہ حضرت مسیح ؑ یہودیوں میں سے تھے اور یہودیوں میں روزہ بڑا مکمل ہوتا ہے اور پھر حضرت مسیح ؑ خود مانتے ہیں کہ کئی قسم کے دیو یعنی روحانی یا جسمانی بیماریاں ایسی ہیں جو روزہ رکھنے والے کی دعا سے دُور ہوتی ہیں اس کے بغیر نہیں ہوتیں.یہودیت اور عیسائیت کے بعد ہندو مذہب کو دیکھا جائے تو ان میں بھی کئی قسم کے برت پائے جاتے ہیں اور ہر قسم کے برت کے متعلق الگ الگ شرائط اور قیود ہیں جن کا تفصیلی ذکر ان کی کتاب’’دھرم سندھو‘‘ میں پایا جاتا ہے.انسا ئیکلو پیڈیا برٹینیکا میں بھی ہندو اور جین مت کے روزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور زرتشتی مذہب کے متعلق بھی لکھا ہے کہ زرتشت نے اپنے پیروئوں کو روزے رکھنے کی تلقین کی تھی.(انسا ئیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Fasting) غرض روزہ روحانی ترقی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمام مذاہب میں مشترک طور پر نظر آتا ہے اور تمام اُمتیں روزوں سے برکتیں حاصل کرتی رہی ہیں بلکہ آجکل تو ایک نئی قسم کا روزہ نکل آیا ہے کہ اگر کسی سے جھگڑا ہوا تو کھانا پینا چھوڑ دیا.گاندھی جی نے انگریز کے مقابلہ میں اس قسم کے کئی مرن برت رکھے تھے.بہرحال مذاہب کی ایک لمبی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضاء حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی اہمیت مذہبی دنیا میں ہمیشہ تسلیم کی جاتی رہی ہے مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جس صورت اورجس شکل میں اسلام نے اس کو پیش
Page 169
کیا ہے وہ باقی مذاہب سے نرالی ہے.اسلام میں روزوں کی یہ صورت ہے کہ ہر بالغ عاقل کو برابر ایک مہینہ کے روزے رکھنے کا حکم ہے سوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص بیمار ہو یا اُسے بیماری کا یقین ہو یا سفر پر ہو یا بالکل بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہو.ایسے لوگ جو بیمار ہوں یا سفر پر ہوں ان کے لئے حکم ہے کہ وہ دوسرے اوقات میں روزہ رکھیں.اور جو بالکل معذور ہو گئے ہوں ان کے لئے کوئی روزہ نہیں.روزہ کی صورت یہ ہے کہ َپوپھٹنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک انسان کوئی چیز نہ کھائے نہ پیئے نہ کم نہ زیادہ اور نہ مخصوص تعلقات کی طرف توجہ کرے.َپوپھٹنے سے پہلے وہ کھانا کھا لے تاکہ اس کے جسم پر غیر معمولی بوجھ نہ پڑے اور غروبِ آفتاب پر روزہ افطار کر دے.صرف شام کو ہی کھانا کھا کر متواتر روزے رکھنا ہماری شریعت نے نا پسند کیا ہے.اس جگہ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ کے متعلق ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف کسی قوم میں کسی رواج کا پایا جانا یا پہلوں میں کسی دستور کا ہونا اس امر کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ آئندہ نسلیں بھی ضرور اس کا لحاظ رکھیں.بیسیوں باتیں ایسی ہیں جو پہلے لوگوں میں موجود تھیں لیکن دراصل وہ غلط تھیں.اور بیسیوں باتیں ایسی ہیں جو آج لوگوں میں پائی جاتی ہیں حالانکہ وہ بھی غلط ہیں.پس محض اس وجہ سے کہ پہلی قومیں کوئی عبادت کرتی رہی ہیں یہ نتیجہ نکالنا کہ آئندہ بھی وہ کی جائے صحیح نہیں.قرآن کریم نے اس اعتراض کے وزن کو قبول کیا ہے اور بتایا ہےکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی اُمّتوں میں روزہ کا وجود اس کی فضیلت کی کوئی دلیل ہے بلکہ اس کے صرف یہ معنے ہیں کہ تم پر یہ کوئی زائد بوجھ نہیں ڈالا گیا بلکہ پہلوں پر بھی یہ بوجھ ڈالا گیا تھا.پس یہ روزوں کی فضیلت کی دلیل نہیں بلکہ روزوں کی اہمیت کی دلیل ہے.روزوں کی فضیلت اور اس کے فوائد پر لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ کے الفاظ میں روشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ روزے تم پر اس لئے فرض کئے گئے ہیں لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ تاکہ تم بچ جائو.اس کے کئی معنے ہو سکتے ہیں.مثلاً ایک معنی تو یہی ہیں کہ ہم نے تم پر اس لئے روزے فرض کئے ہیں تاکہ تم ان قوموں کے اعتراضوں سے بچ جائو جو روزے رکھتی رہی ہیں.جو بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتی رہی ہیں.جو موسم کی شدت کو برداشت کر کے خدا تعالیٰ کو خوش کرتی رہی ہیں.اگر تم روزے نہیں رکھو گے تو وہ کہیں گی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم باقی قوموں سے روحانیت میں بڑھ کر ہیں لیکن وہ تقویٰ تم میں نہیں جو دوسری قوموں میں پایا جاتا تھا.غرض اگر اسلام میں روزے نہ ہوتے تو باقی مسلمان دوسری قوموں کے سامنے ہدفِ ملامت بنے رہتے.عیسائی کہتے یہ بھی کوئی مذہب ہے اس میں روزے تو ہیں ہی نہیں جن سے قلوب کی صفائی ہوتی ہے جن کے ساتھ روحانی ساکھ بیٹھتی ہے جن کے ذریعہ انسان بدی سے بچتا ہے.
Page 170
یہودی کہتے کہ ہم نے سینکڑوں سال روزے رکھے لیکن مسلمانوں میں روزے نہیں.اسی طرح زرتشتی ہندو اور دوسری سب قومیں کہتیں.اسلام بھی کوئی مذہب ہے اس میں روزے نہیں.ہم روزے رکھتے ہیں اور اس طرح خدا تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں.غرض ساری دنیا مسلمانوں کے مقابلہ میں آجاتی اور کہتی مسلمانوں میں روزے کیوں نہیں؟ پس فرمایا.اے مسلمانو! ہم تم پر روزے فرض کرتے ہیں لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ تاکہ تم دشمن کے اعتراضات سے بچ جائو.اگر اسلام میں روزہ نہ ہوتا یا تم روزے نہ رکھتے تو غیر مذاہب والے تم پر جائز طور پر اعتراض کرتے اور تم ان کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتے.لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ میں دوسرا اشارہ اس امر کی طرف کیا گیا ہے کہ اس ذریعہ سے خدا تعالیٰ روزہ دار کا محافظ ہو جاتا ہے.کیونکہ اِتِّقَاء کے معنے ہیں ڈھال بنانا.وقایہ بنانا.نجات کا ذریعہ بنانا.پس اس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ تم پر روزے رکھنے اس لئے فرض کئے گئے ہیں تاکہ تم خدا تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنا لو اور ہر شر سے اور ہر خیر کے فقدان سے محفوظ رہو.ضعف دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک تویہ کہ انسان کو کوئی شر پہنچ جائے اور دوسرے یہ کہ کوئی نیکی اس کے ہاتھ سے جاتی رہے.جیسے کسی کو کوئی مار بیٹھے تو یہ بھی ایک شر ہے.اور یہ بھی شر ہے کہ کسی کے ماںباپ اس سے ناراض ہو جائیں حالانکہ اگر کسی کے والدین ناراض ہو کر اس کے گھر سے نکل جائیںتو بظاہر اس کا کوئی نقصان نظر نہیں آتا بلکہ ان کے کھانے کا خرچ بچ سکتا ہے.لیکن ماں باپ کی رضا مندی ایک خیر اور برکت ہے اور جب وہ ناراض ہو جائیں تو انسان ایک خیر سے محروم ہو جاتا ہے.اِتِّقَاء ان دونوں باتوں پر دلالت کرتا ہے اور متقی وہ ہے جسے ہر قسم کی خیر مل جائے اور وہ ہرقسم کی ذلّت اور شر سے محفوظ رہے.اس سے آگے پھر شر کا دائرہ بھی ہر کام کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اگر کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو اس کا شر سے محفوظ رہنا یہی ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش نہ آئے اور وہ بحفاظت منزلِ مقصود پر پہنچ جائے.اسی طرح روزے کے سلسلہ میں بھی ایسے ہی خیر وشر مراد ہو سکتے ہیں جن کا روزے سے تعلق ہو.روزہ ایک دینی مسئلہ ہے یا بلحاظ صحتِ انسانی دنیوی امور سے بھی کسی حد تک تعلق رکھتا ہے پس لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ کے یہ معنے ہوئے کہ تا تم دینی اور دنیوی شُرور سے محفوظ رہو.دینی خیر و برکت تمہارے ہاتھ سے نہ جاتی رہے یا تمہاری صحت کو نقصان نہ پہنچ جائےکیونکہ بعض دفعہ روزے کئی قسم کے امراض سے نجات دلانے کا بھی موجب ہو جاتے ہیں.آجکل کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بڑھاپا یا ضعف آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انسان کے جسم میں زائد مواد جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے بیماری یا موت پیدا ہو تی ہے.بعض نادان تو اس خیال میں اس حد تک ترقی کر گئے
Page 171
ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس دن ہم زائد مواد کوفنا کرنے میں کامیاب ہو گئے اس دن موت بھی دنیا سے اُٹھ جائےگی.یہ خیال اگرچہ احمقانہ ہے تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تھکان اور کمزوری وغیر ہ جسم میں زائد مواد جمع ہونے ہی سے پیدا ہوتی ہے.اورروزہ اس کے لئے بہت مفید ہے.میں نے خود دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں جب روزے رکھے جائیں تو دورانِ رمضان میں بے شک کچھ کوفت محسوس ہوتی ہے مگر رمضان کے بعد جسم میں ایک نئی قوت اور تروتازگی کا احساس ہونے لگتا ہے.یہ فائدہ تو صحتِ جسمانی کے لحاظ سے ہے مگر روحانی لحاظ سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے.اسی لئے روزوں کے ذکر کے بعد خدا تعالیٰ نے دعائوں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی دعائوں کو سنتا ہوں پس روزے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے والی چیز ہیں اور روزے رکھنے والا خدا تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے جو اسے ہر قسم کے دکھوں اور شر ور سے محفوظ رکھتا ہے.پھر روزے کے ذریعہ دکھوں سے انسان اس طرح بھی بچتا ہے کہ (۱)جب وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے لئے تکلیف میں ڈالتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا سے اُسے بچالیتا ہے.(۲) جب وہ فاقے رہ کر بھوک کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو اپنے غریب بھائیوں کی خبر گیری کرتا ہے اور ان کا ہلاکت سے بچنا خود اُسے بھی ہلاکت سے بچا لیتا ہے کیونکہ بعض افرادِ قوم کے بچنے سے آخر ساری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے.یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں بہت کثرت سے صدقہ و خیرات کیاکرتے تھے.احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں آپ تیز چلنے والی آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے(بخاری کتاب الصوم باب اجود ما کان النبیؐ یکون فی رمضان) اور درحقیقت یہ قومی ترقی کا ایک بہت بڑا گُر ہے کہ انسان اپنی چیزوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے.تمام قسم کی تباہیاں اُسی وقت آتی ہیں جب کسی قوم کے افراد میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ان کی چیزیں انہی کی ہیں دوسروں کا ان میں کوئی حق نہیں اور ان سے فائدہ اُٹھانے کا حق اُنہی کو ہے جن کو وہ چیزیں دی گئی ہیں.دنیا کے نظام کی بنیاد اس اصل پر ہے کہ میری چیز دوسرا استعمال کرے اور رمضان اس کی عادت ڈالتا ہے.روپیہ ہمارا ہے.کھانے پینے کی چیزیں ہماری ہیں مگر حکم یہ ہے کہ دوسروں کو ان سے فائدہ پہنچائو اور کھلائو کیونکہ اس سے دنیا کے تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے.پھر روزوں کے ذریعہ انسان ہلاکت سے اس طرح بھی محفوظ رہتا ہے کہ روزے انسان کے اندر مشقت برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرتے ہیں اور جو لوگ ہر قسم کی مشقت برداشت کرنے کے عادی ہوں وہ مشکلات کے
Page 172
آنے پر ہمّت نہیں ہارتے بلکہ دلیری سے ان کا مقابلہ کرتے اور کامیابی حاصل کرتے ہیں.دنیوی گورنمنٹوں میں بھی ایک ریزرو فوج ہوتی ہے جو سال میں ایک یا دو مہینے کام کرتی ہے اور جب جنگ کا موقعہ آتا ہے تو چونکہ اس کو مشق کروائی ہوئی ہوتی ہے اس لئے فوراً اسے بلوالیا جاتا ہے.چونکہ عام طور پر تمام مسلمان بارہ مہینے روزے نہیں رکھتے اور نہ ہی تہجد پڑھتے ہیں اس لئے رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ہدایت فرما دی کہ تمام مسلمان اس ماہ میں روزوں کی مشق کریں جس طرح وہ فوج جو مشق کرتی رہتی ہے دشمن کی فوج سے شکست نہیں کھاتی اسی طرح جس قوم کے لوگ متّقی اور نیک ہوتے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کے لئے ہر ایک چیز کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں شیطان کی مجال نہیں ہوتی کہ ان کو زک دے سکے یہی وجہ ہے کہ جب تک تمام مسلمان روحانی سپاہی تھے شیطان نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا لیکن جب خال خال رہ گئے تو اس وقت ان پر حملہ کیا گیا اور شیطان نے ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈال کر ان کو تباہ کر دیا.پس روزے قوم میں قربانی کی عادت پید ا کرنے کا موجب ہوتے ہیں.دین کی خدمت کے لئے بالعموم مومنوں کو گھروں سے نکلنا پڑتا ہے.اور تبلیغی جہاد میں کھانے پینے کی تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے.غرباء کو تو ایسی تکالیف برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے مگر امراء کو اس کی عادت نہیں ہوتی.پس روزوں کے ذریعہ ان کو بھی بھوک اور پیاس کی برداشت کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ جس دن خدا تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے کہ اے مسلمانو! آئو اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو تو وہ سب اکٹھے اُٹھ کھڑے ہوں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں بغیر کسی قسم کا بوجھ محسوس کئے اپنے آپ کو پیش کر دیں.پس روزوں کا یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کو نیکی کے لئے مشقّت برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے.انسان دنیا میں کئی قسم کے کام کرتا ہے.وہ محنت و مشقّت بھی کرتا ہے.وہ آوارگی بھی کرتا ہے وہ اِدھر اُدھر بھی پھرتا ہے وہ گپیں بھی ہانکتا ہے.بالکل فارغ نہ انسانی دماغ رہتا ہے نہ اس کا جسم.کچھ نہ کچھ کام انسان ضرور کرتا رہتا ہے.مگر بعض لغو کام ہوتے ہیں بعض مضر اور بعض مفید اور بعض بہت ہی اچھے.لیکن رمضان انسان کو ایک ایسے کام کی عادت ڈالتا ہے جس کے نتیجہ میں اسے نیک کاموں میں مشقّت برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے انسانی زندگی کی راحت اور آرام کی چیزیں کیا ہوتی ہیں یہی کھانا پینا سونا اور جنسی تعلقات.تمدن کا اعلیٰ نمونہ جنسی تعلقات ہیں.جن میں دوستوں سے ملنا اور عزیزوں سے تعلقات رکھنا بھی شامل ہے مگر جنسی تعلقات میں سب سے زیادہ قریبی تعلق میاںبیوی کا ہے پس انسانی آرام انہی چند باتوں میں مضمر ہے کہ وہ کھاتا ہے.
Page 173
وہ پیتا ہے.وہ سوتا ہے.اور وہ جنسی تعلقات قائم رکھتا ہے.کسی صوفی نے کہا ہے کہ تصّوف کی جان کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا ہے اور رمضان اس تصّوف کی ساری جان کا نچوڑ اپنے اندر رکھتا ہے کم سونا آپ ہی اس میں آجاتا ہے کیونکہ رات کو تہجد کے لئے اُٹھنا پڑتا ہے.کم کھانا بھی ظاہر بات ہے کیونکہ سارا دن فاقہ کرنا پڑتا ہے.اور جنسی تعلقات کی کمی بھی ظاہر ہے پھر کم بولنا بھی رمضان میں آجاتا ہے.اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖوسلم نے ایک دفعہ فرمایا.روزہ یہ نہیں کہ انسان اپنا منہ کھانے پینے سے بند رکھے بلکہ روزہ یہ ہے کہ تُو لغو باتیں بھی نہ کرے.(بخاری کتاب الصوم باب من لم یدع قول الزور والعمل بہ فی الصوم).پس روزہ دار کے لئے بیہودہ باتوں سے بچنا لڑائی جھگڑے سے بچنا اور اسی طرح کی اَور لغو باتوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہوتاہے.اس طرح کم بولنا بھی رمضان میں آگیا.گویا کم کھانا.کم بولنا.کم سونا اور جنسی تعلقات کم کرنا یہ چاروں باتیں رمضان میں آگئیں اور یہ چاروں چیزیں نہایت ہی اہم ہیں.اور انسانی زندگی کا ان سے گہرا تعلق ہے پس جب ایک روزہ دار اِن چاروں آرام و آسائش کے سامانوں میں کمی کرتا ہے تو اس میں مشقّت برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کے ہر دور میں مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا اور کامیابی حاصل کرتا ہے.پھر لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ میں ایک اور فائدہ یہ بتایا کہ روزہ رکھنے والا برائیوں اور بدیوں سے بچ جاتا ہے اور یہ غرض اس طرح پوری ہوتی ہے کہ دنیا سے انقطاع کی وجہ سے انسان کی روحانی نظر تیز ہو جاتی ہے اور وہ ان عیوب کو دیکھ لیتا ہے جو اُسے پہلے نظر نہ آتے تھے.اسی طرح گناہوں سے انسان اس طرح بھی بچ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا ہے روزہ اس چیز کا نام نہیں کہ کوئی شخص اپنا منہ بند رکھے اور سارا دن نہ کچھ کھائے اور نہ پیئے بلکہ روزہ یہ ہے کہ مونہہ کو کھانے پینے سے ہی نہ روکا جائے بلکہ اُسے ہر روحانی نقصان دہ اور ضر ررساں چیز سے بھی بچایا جائے.نہ جھوٹ بولا جائے.نہ گالیاں دی جائیں.نہ غیبت کی جائے.نہ جھگڑا کیا جائے.اب دیکھو زبان پر قابو رکھنے کا حکم تو ہمیشہ کے لئے ہے لیکن روزہ دار خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر کوئی شخص ایک مہینہ تک اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے تو یہ امر باقی گیارہ مہینوں میں بھی اس کے لئے حفاظت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے.اور اس طرح روزہ اُسے ہمیشہ کے لئے گناہوں سے بچا لیتا ہے.پھر لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ میں روزوں کا ایک اَور فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے نتیجہ میں تقویٰ پر ثباتِ قدم حاصل ہوتا ہے اور انسان کو روحانیت کے اعلیٰ مدارج حاصل ہوتے ہیں.چنانچہ روزوں کے نتیجہ میں صرف امراء ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتے بلکہ غرباء بھی اپنے اندر ایک نیا روحانی انقلاب محسوس کرتے ہیں.اور وہ بھی اللہ تعالیٰ
Page 174
کے وصال سے لطف اندوز ہوتے ہیں.غرباء بیچارے سارا سال تنگی سے گذارہ کرتے ہیں اور بعض دفعہ انہیں کئی کئی فاقے بھی آجاتے ہیں.اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعہ انہیں توجہ دلائی ہے کہ وہ ان فاقوں سے بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں.اور خدا تعالیٰ کے لئے فاقوں کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلصَّوْمُ لِیْ وَاَنَا اُجْزٰی بِہٖ یعنی ساری نیکیوں کے فوائد اور ثواب الگ الگ ہیں لیکن روزہ کی جزاء خود میری ذات ہے.اور خدا تعالیٰ کے ملنے کے بعد انسان کو اور کیا چاہیے! غرض روزوں کے ذریعہ غربا ء کو یہ نکتہ بتایا گیا ہے کہ ان تنگیوں پر بھی اگر وہ بے صبر اور ناشکر ے نہ ہوں اور حرف شکایت زبان پر نا لائیں جیسا کہ بعض نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے کیا دیا ہے کہ نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں تو یہی فاقے ان کے لئے نیکیاں بن جائیں گی.اور ان کا بدلہ خود خدا تعالیٰ ہو جائےگا.پس اللہ تعالیٰ نے روزوں کو غرباء کے لئے تسکین کا موجب بنایا ہے تاکہ وہ مایوس نہ ہوں او ریہ نہ کہیں کہ ہماری فقرو فاقہ کی زندگی کس کام کی! اللہ تعالیٰ نے روزہ میں ا نہیں یہ ُگر بتایا ہے کہ اگر وہ اس فقروفاقہ کی زندگی کو خدا تعالیٰ کی رضاء کے مطابق گذاریں تو یہی انہیں خدا تعالیٰ سے ملا سکتی ہے.دنیا میں اس قدر لوگ امیر نہیں جتنے غریب ہیں اور تمام دینی سلسلوں کی ابتداء بھی غرباء سے ہی ہوئی ہے اور انتہا بھی غرباء پر ہی ہوئی.بلکہ قریباً تمام انبیاء بھی غرباء میں سے ہی ہوئے ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بڑے آدمی نہ تھے.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بڑے آدمی نہ تھے.حضرت مسیح موعو د علیہ الصلوٰۃ و السلام بھی کوئی امیر کبیر نہ تھے.آپ کی جائیداد کی قیمت قادیان کے ترقی کرنے کے باعث بڑھ گئی.ورنہ اس کی قیمت خود آپ نے دس ہزار روپیہ لگائی تھی اور اتنی مالیت کی جائیداد سے کونسی بڑی آمد ہوسکتی ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑے آدمی نہ تھے.اگرچہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ بعد میںبڑا بنا دیتا ہے لیکن یہ سب کچھ بعد میں فضل کے طور پر ہوا.ابتداء میں تمام سلسلوں کے بانی غریب ہی ہوئے امراء اور بادشاہ نہیں ہوئے.بیشک درمیانی طبقہ کے لوگوں میں سے بھی بعض دفعہ انبیاء ہوتے رہے لیکن بادشاہ صرف چند ایک ہی ہوئے.جیسے حضرت دائود علیہ السلام یاحضرت سلیمان علیہ السلام.مگر یہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ کسی سلسلہ کے بانی ہوں.پھر دنیا کی اسّی فیصدی آبادی غریب ہے.اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کثرت کی دلجوئی رمضان کے ذریعہ کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ فاقہ کش کو خدا تعالیٰ نہیں مل سکتا اگر ایسا ہوتا تو رمضان کے نتیجہ میں کیوں ملتا؟ پس وہ غرباء جو سمجھتے ہیں کہ ان کی عمر رائیگاں گئی.اللہ تعالیٰ نے اُنہیں رمضان کے ذریعہ بتایا ہے کہ وہ انہی فاقوں میں سے گذر کر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیوض حاصل کر سکتے ہیں بشرطیکہ فاقہ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں اور اس کے متعلق اپنی زبان پرکوئی حرفِ شکایت نہ لائیں.
Page 175
اس کے مقابلہ میں روزہ امیر لوگوں کے لئے تقویٰ کے حصول کا ذریعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک انسان جس کے پاس کھانے پینے کے تمام سامان موجو دہوتے ہیں محض اللہ تعالیٰ کی رضاء کے لئے اپنے آپ کو فاقہ میں ڈالتا ہے اور خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے کچھ نہیں کھاتا اور جو حلال چیزیں خدا تعالیٰ نے اُسے دی ہیں انہیں بھی استعمال نہیں کرتا.اس کے گھر میں گھی، گوشت ، چاول وغیرہ کھانے کی تمام ضروریات موجو د ہوتی ہیں مگر وہ خدا تعالیٰ کے لئے انہیں ترک کر دیتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود یہ جذبہ پیدا ہوتاہے کہ جب میں نے حلال چیزوں کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے چھوڑ دیا ہے تو میں ان چیزوں کی کیوں خواہش کروں جنہیں خدا تعالیٰ نے حرام قرار دیاہوا ہے؟ اس طرح اس کے اندر ضبطِ نفس کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو نیکیوں کے میدان میں بڑھاتا چلا جاتا ہے.روزوں کا ایک روحانی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے انسان خدا تعالیٰ سے مشابہت اختیار کرلیتا ہے.خدا تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیند سے پاک ہے.انسان ایسا تو نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی نیند کو بالکل چھوڑ دے مگر وہ اپنی نیند کے ایک حصہ کو روزوں میں خدا تعالیٰ کےلئے قربان ضرور کرتا ہے.سحری کھانے کے لئے اُٹھتا ہے.تہجد پڑھتا ہے.عورتیں جو روزہ نہ بھی رکھیں وہ سحری کے انتظام کے لئے جاگتی ہیں.کچھ وقت دعائوں میں اور کچھ نماز میں صرف کرنا پڑتا ہے اور اس طرح رات کا بہت کم حصہ سونے کے لئے باقی رہ جاتا ہے اور کام کرنے والوں کے لئے تو گرمی کے موسم میں دو تین گھنٹے ہی نیند کے لئے باقی رہ جاتے ہیں.اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے.اسی طرح اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے.انسان کھانا پینا بالکل تو نہیں چھوڑ سکتا مگر پھر بھی رمضان میں اللہ تعالیٰ سے وہ ایک قسم کی مشابہت ضرور پیدا کر لیتا ہے پھر جس طرح اللہ تعالیٰ سے خیر ہی خیر ظاہر ہوتا ہے اسی طرح انسان کو بھی روزوں میں خاص طور پر نیکیاں کرنے کا حکم ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.جو شخص غیبت، چغلخوری اور بدگوئی وغیرہ بُری باتوں سے پرہیز نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا.گویا مومن بھی کوشش کرتا ہے کہ اس سے خیر ہی خیر ظاہر ہو.اور وہ غیبت اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے.اس طرح وہ اس حد تک خدا تعالیٰ سے مشابہت پیدا کر لیتا ہے جس حد تک ہو سکتی ہے.اور یہ ظاہر ہے کہ ہر چیز اپنی مثل کی طرف دوڑتی ہے.فارسی میں ضرب المثل ہے کہ ’’کند ہم جنس باہم جنس پرواز‘‘ پس روزہ کا ایک روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے اعلیٰ درجہ کا اتصال ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کا محافظ بن جاتا ہے.
Page 176
پھر روزوں کا روحانی رنگ میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا الہام انسانی قلب پر نازل ہوتا ہے اور اس کی کشفی نگاہ میں زیادہ جِلا اور نور پیدا ہو جاتا ہے.درحقیقت اگر غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی عادت تو نہیں مگر اس میں عادت سے ایک مشابہت ضرور پائی جاتی ہے.انسان کی طرح اس کی آنکھیں تو نہیں مگر وہ بصیر ضرور ہے اس کے کان نہیں مگر وہ سمیع ضرور ہے اسی طرح گو اس میں کوئی عادت نہیں پائی جاتی مگر اس میں یہ بات ضرور پائی جاتی ہے کہ جب وہ ایک کام کرتا ہے تو اُسے دوہراتا ہے.انسان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے.بعض لوگوں کو ہاتھ یا پیر ہلانے کی عادت ہوتی ہے اور وہ انہیں بار بار ہلاتے ہیں اور عادت کے یہی معنے ہوتے ہیں کہ کوئی بات باربار کی جائے اور یہ بات اللہ تعالیٰ میں بھی ہے کہ جب وہ ایک خاص موقعہ پر اپنا فضل نازل کرتا ہے تواس موقعہ پر باربارفضل کرتاہے.اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ماتحت چونکہ رمضان کے مہینہ میں قرآن کریم نازل ہوا تھا.اس لئے اگر اس رسولؐ کی اتباع کی جائے جس پر قرآن کریم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی عادت سے مشابہت رکھنے والی صفت کے ماتحت ان لوگوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی وجہ سے دنیا سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس سے تعلقات نہیں رکھتے.کھانے پینے اور سونے میں کمی کرتے ہیں.بے ہودہ گوئی وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے الہام سے نوازتا اور ان پررئویا صادقہ اور کشوفِ صحیحہ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اسرار غیبیہ سے مطلع کرتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃو السلام کا بھی ایک الہام ہے کہ پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی اس میں بھی وہی عادت والی بات بیان کی گئی ہے.خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ بہار میں اپنی رحمت کی شان دکھائی تھی اس لئے جب پھر موسم بہار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہتی ہے کہ اب کے میرے بندے کیا کہیں گے اس لئے ہم پھر اپنی شان دکھاتے ہیں.اور اگر بندے اس سے فائدہ اٹھائیں تو اگلی بہار میں پھر وہی انعام نازل ہوتا ہے.غرض کلامِ الٰہی کو اگر درخت تصّور کر لیا جائے تو جو صفتِ الہٰی عادت کے مشابہ ہے وہ ہر رمضان میں اسے جھنجھوڑتی ہے اور ا س سے مومنوں کو تازہ بتازہ پھل حاصل ہوتے ہیں.پھر روزوں سے اس رنگ میں بھی روحانیت ترقی کرتی ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے کھانا پینا ترک کرتا ہے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے اس کی راہ میں مرنے کو تیار ہے.اور جب وہ اپنی بیوی سے مخصوص تعلقات قطع کرتا ہے تو اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنی نسل کو بھی قربان کر
Page 177
دینے کےلئے تیار ہے اور جب وہ روزوں میں ان دونوں اقسام کے نمونے پیش کر دیتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی لقاء کا مستحق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق قائم ہونے اور روحانیت کے مضبوط ہوجانے کی وجہ سے وہ شخص ہمیشہ کے لئے گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے.پھر رمضان کے ذریعہ استقلال کی عادت بھی ڈالی جاتی ہے کیونکہ یہ نیکی متواتر ایک عرصہ تک چلتی ہے.انسان دن میںکئی کئی مرتبہ کھانے کا عادی ہوتا ہے.غرباء اور امراء شہری اور دیہاتی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عام ایام میں کئی دفعہ کھاتے پیتے ہیں مگر رمضان میں تمام کھانے سمٹ سمٹاکر صرف دو بن جاتے ہیں.اسی طرح جہاں دوسرے ایام میں وہ ساری رات سوئے رہتے ہیں وہاں رمضان کے ایام میں انہیں تہجد اور سحری کے لئے اُٹھنا پڑتا ہے اور دن کو بھی قرآن کریم کی تلاوت میں اپنا کافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے.غرض رمضان کے ایام میں اپنی عادت کی بہت کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے اور یہ قربانی ایک دن نہیں دو دن نہیں بلکہ متواتر ایک مہینہ تک بغیر ناغہ کے کرنی پڑتی ہے.پس روزوں سے استقلال کا عظیم الشان سبق ملتا ہے.اور درحقیقت بغیر مستقل قربانیوں کے کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پا سکتا کیونکہ حقیقی محبت جوش دلانے سے تعلق نہیں رکھتی اور نہ وہ عارضی ہوتی ہے بلکہ حقیقی محبت استقلال سے تعلق رکھتی ہے.یہی وجہ ہے کہ جب ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو معلوم ہو اکہ آپ کی ایک بیوی نے چھت سے ایک رسّہ اس لئے لٹکا رکھا ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے انہیں اونگھ آنے لگے تو اس کا سہارا لے لیں تو آپ نے فرمایا یہ کوئی عبادت نہیں.عبادت وہی ہے جسے انسان بشاشت سے ادا کر سکے.اور جس کے نتیجہ میں ایسا ملال پیدا نہ ہو.جو اس کے دوام اور استقلال کو قطع کرنے کا موجب بن جائے.(بخاری کتاب التہجد باب ما یکرہ من التشدید فی العبادۃ).اسی طرح روزوں کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ مومنوں کو ایک مہینہ تک اپنے جائز حقوق کو بھی ترک کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے.انسان گیارہ مہینے حرام چھوڑنے کی مشق کرتا ہے مگر بارھویں مہینہ میں وہ حرام نہیں بلکہ حلال چھوڑنے کی مشق کرتا ہے.یعنی روزوں کے علاوہ دوسرے ایام میں ہم یہ نمونہ دکھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کےلئے ہم کس طرح حرام چھوڑسکتے ہیں.مگر روزوں کے ایام میں ہم یہ نمونہ دکھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے کس طرح حلال چھوڑ سکتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حلال چھوڑنے کی عادت پیدا کئے بغیر دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی.دنیا میں اکثر فساد اس لئے نہیں ہوتے کہ لوگ حرام چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ اکثر فساداس لئے ہوتے ہیں کہ لوگ حلال کو بھی ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے.وہ لوگ بہت ہی کم ہیں جو ناجائز
Page 178
طور پر کسی کا حق دبائیں مگر وہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہیں جو لڑائی اور جھگڑے کو پسند کرلیں گے مگر اپنا حق چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوںگے.سینکڑوں پاگل اور نادان دنیا میں ایسے ہیں جو اپنا حق حاصل کرنے کے لئے دنیا میں عظیم الشان فتنہ و فساد پیدا کر دیتے ہیں.اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا کا امن برباد ہورہا ہے.حالانکہ اگر وہ ذاتی قربانی کریں تو بہت سے جھگڑے اور فساد مٹ سکتے ہیں اور نہایت خوشگوار امن قائم ہو سکتا ہے.پس رمضان کا مہینہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم صرف حرام ہی نہ چھوڑو بلکہ خدا تعالیٰ کے لئے اگر ضرورت پڑ جائے تو حلال یعنی اپنا حق بھی چھوڑ دو.تاکہ دنیا میں نیکی قائم ہو اور خدا تعالیٰ کا نام بلند ہو.یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی عبادتیں اپنے اندر کئی قسم کے سبق رکھتی ہیں.بعض سبق ایسے ہوتے ہیں جو ہر عبادت سکھاتی ہے اور بعض سبق ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ عبادتوں کی نسبت سے پیدا ہوتے ہیں.اور بعض سبق ایسے ہیں جو ساری عبادتوں کی مجموعی حالت سے پیدا ہوتے ہیں.بعینہٖ اسی طرح خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ عالم میں ہمیں یہ نقشہ نظر آتا ہے کہ اس کا ہر فرد اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے پھر دو افراد مل کر اپنے اندر حقیقت رکھتے ہیں.پھر دو سے زیادہ افراد مل کر ایک حقیقت پیدا کرتے ہیں.پھر سارا عالم اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے یہی حال عبادتوں کا ہے.اور جس طرح قانونِ قدرت میں ایک ترتیب اور ربط موجود ہے اسی طرح عبادتوں میں بھی ربط ہے مگر یہ بات صرف شریعتِ اسلامیہ میں ہی پائی جاتی ہے باقی شرائع میں نہیں.ان میں نماز.زکوٰۃ اور روزہ کی قسم کی عبادتیں ہیں مگر ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں.وہ ایسی ہی ہیں جیسے بکھری ہوئی اینٹیں.لیکن شریعت اسلامیہ کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا ہر حکم اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے پھر سارے کے سارے احکام مل کر اپنے اندر ایک اور حکمت رکھتے ہیں.اس کی ایک مثال نماز اور روزہ ہے.نماز اپنی ذات میں ایک سبق رکھتی ہے اور روزہ بھی اپنی ذات میں ایک سبق رکھتا ہے مگر پھر نماز اور روزہ مل کر ایک اور سبق رکھتے ہیں.اگر نماز نہ ہوتی صرف روزے ہوتے تو یہ سبق رہ جاتا.اور اگر روزے نہ ہوتے صرف نماز ہی ہوتی تب بھی یہ سبق رہ جاتا.بیشک روزے اپنی ذات میں مفید ہیں اور نماز اپنی ذات میں مفید ہے جس طرح اسلام کی ساری عبادتیں اپنی اپنی ذات میں مفید ہیں لیکن نماز اور روزہ مل کر ایک نیا سبق دیتے ہیں جس کا میں اس موقعہ پر ذکر کر رہا ہوں.نماز کا اصل مقام طہارت ہے جسے وضو کی حالت کہتے ہیں.اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وضو کر کے نماز کے لئے بیٹھ جاتاہے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے (مسلم کتاب المساجد باب فضل الصلاۃ المکتوبۃ فی جماعۃ و فضل انتظار الصلوٰۃ...).نماز اس حالت کا انتہائی مقام ہے.ورنہ اصل نماز
Page 179
مومن کی وہ قلبی کیفیت ہے جو وضو سے تعلق رکھتی ہے.اب یہ دیکھنا چاہیے کہ وضو کی کیا حقیقت ہے؟ وضو کے ذریعہ جو فعل ہم کرتے ہیں وہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو خواہ وہ پیشاب پاخانہ کے رنگ میں خارج ہو خواہ مرد عورت کے تعلقات کے ذریعہ سے خارج ہو یا اور ایسے رنگوں سے خارج ہو جن سے طہارت کو نقصان پہنچتا ہے.غرض وضو کا مدار کسی چیز کے جسم سے نہ نکلنے پر ہے.اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو.لیکن روزہ کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم کے اندر داخل نہ ہو.بیشک روزہ میں مرد و عورت کے تعلقات سے بھی روکا گیا ہے مگر یہ اس لئے ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان کی کلّی توجہ اور طرف نہ ہو.ورنہ روزہ کا اصل مدار کسی چیز کے جسم میں داخل نہ ہونے پر ہے.اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ روزہ کا مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم میںداخل نہ ہو.اگر صرف نماز ہی ہوتی اور وضو صرف ظاہری صفائی ہوتا تو کہا جاتا کہ اس سے مراد صرف ہاتھ منہ اور پائوں کا دھونا ہے.اسی طرح اگر روزہ ہوتا اور کوئی چھوٹی موٹی چیز کھالی جاتی تو کہا جاسکتا تھا کہ روزہ سے مراد فاقہ کرانا ہے.لیکن جسم سے کچھ خارج ہونے سے وضو کا باطل ہو جانا اور کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے روزہ کا ٹوٹ جانا بتاتا ہے کہ کسی چیز کے خارج ہونے کا نماز سے اور کسی چیزکے اندر داخل ہونے کا روزہ سے تعلق ہے.اور ان دونوں کو ملا کر یہ لطیف بات نکلتی ہے کہ انسان طہارت میںاس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دو احتیاطیں نہ کرے.یعنی بعض چیزیں اپنے جسم سے نکلنے نہ دے اور بعض چیزیں داخل نہ ہونے دے.اگر ہم ان دو باتوں کا لحاظ رکھ لیں کہ بعض چیزوں کو جسم سے نکلنے نہ دیں اور بعض کو داخل نہ ہونے دیں تو طہارت کامل ہو جاتی ہے.نماز اور روزہ سے مجموعی طور پر انسان کو یہ گُر سکھایا گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ امر مدِّنظر رکھنا چاہیے کہ بعض چیزوں کے جسم سے نکلنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے ان کو نکلنے نہ دے اور بعض چیزوں کے جسم میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے انہیں داخل نہ ہونے دے.اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی گندی چیزیں ہیں جن کا نکلنا روحانیت کے لحاظ سے مضر ہوتا ہے.دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گند کا نکلنا ہی اچھا ہوتا ہے.کیا ایسے گند بھی ہیں جن کا نہ نکلنا اچھا ہوتا ہے.اس کے متعلق ہمیں قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی تشریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گند ایسے بھی ہیں جن کا نہ نکلنا ہی اچھا ہوتا ہے.مثلاً کسی کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہے.اگر کسی موقعہ پر اسے سخت غصہ آگیا مگر وہ اسے نکلنے نہیں دیتا تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْکَاظِمِیْنَ الْغَیْظَ (اٰل عمران :۱۳۵) نیک اور متقی انسان کو بھی غصہ آجاتا ہے مگر وہ اسے
Page 180
روک لیتا ہے.جیسے نماز کے وقت اس بات کا لحاظ رکھ لیتا ہے کہ اس وقت ایسی چیزیں ظاہر نہ ہوں جو وضو کو باطل کر دیں.بعض کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ روک دینے سے کم نکلتی ہیں اور اگر انہیں نکلنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا جائے تو بڑھ جاتی ہیں غصہ بھی ایسی ہی کیفیات میں سے ہے.ہمارے ہاں محاورہ بھی یہی ہے.کہتے ہیں کہ اب تو آپ نے غصہ نکال لیا ہے اب جانے دو.یعنی گالی گلوچ یا مار پیٹ کے ذریعہ سے غصہ کا اظہار کر لیا ہے.لیکن اگر وہ اسے دبالیتا اور روک لیتا تو وہ اس کے لئے نیکی ہو جاتی ہے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں کوئی بُرا خیال پیدا ہو مگر وہ اسے روک لے اور اس پر عمل نہ کرے تو یہ اس کے لئے نیکی ہو جاتی ہے(مسلم کتا ب الایمان باب اذاھم العبد بحسنۃ کتبت و اذاھمّ بسیئۃ لم تکتب ) غرض قلب کے بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ اگر انہیں ظاہر کیا جائے تو طہارت باطل ہو جاتی ہے.لیکن اگر ان کو دل ہی میں رکھیں تو نیکی بن جاتی ہے.یہ سبق نماز سے حاصل ہوتا ہے.دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی چیز جسم میں داخل نہ ہونے دی جائے اس کی مثال جھوٹ استہزاء چغلخوری اور غیبت وغیرہ کی باتیں ہیں.ان کا نہ سننا بھی نیکی ہوتا ہے.کیونکہ ایسی باتیں انسان کو روحانیت سے عاری کر دیتی ہیں.پس اخلاقِ فاضلہ مکمل کرنے کے لئے ان دونوں کا خیال رکھناضروری ہوتا ہے.کہ بعض قسم کے گند وںکو باہر نہ نکلنے دیا جائے اور بعض کو اندر داخل نہ ہونے دیا جائے.روزہ ہمارے لئے یہ سبق رکھتا ہے کہ ہم ان تمام ناپاک اور گندی باتوں سے بچیں جن کو اپنے اندر داخل کرنے سے ہماری روحانیت باطل ہو جاتی ہے.اور ہم اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جاتے ہیں.اس سوال کا جواب کہ روزے صرف رمضان کے مہینہ میں ہی کیوں رکھوائے جاتے ہیں.سارے سال پر ان کو کیوں نہ پھیلا دیا گیا یہ ہے کہ جب تک تواتر اور تسلسل نہ ہو صحیح مشق نہیں ہوسکتی.ہر مہینہ میں اگر ایک دو دن کا روزہ رکھ دیا جاتا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا.ایک وقت کے کھانے میں تو بعض اوقات سیر وغیرہ کے باعث بھی دیر ہو جاتی ہے یا بعض اوقات اور مصروفیتوں کے باعث بھی کھانا نہیں کھایا جا سکتا.مگر کیا اس سے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے؟ حکومت بھی فوجیوں سے متواتر مشق کراتی ہے.یہ نہیں کہ ہر مہینہ میں ایک دن ان کی مشق کے لئے رکھ دے.غرض جو کام کبھی کبھی کیا جائے اس سے مشق نہیں ہو سکتی.مشق کے لئے مسلسل کام کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے پورے ایک ماہ کے روزے مقرر فرما دیئے تاکہ مومنوں کو خدا تعالیٰ کے لئے بھوکا پیاسا رہنے اور رات کو عبادت کےلئے اُٹھنے اور دن کو ذکرِ الٰہی اور تلاوت ِقرآن کرنے کی عادت ہو اور ان کی روحانی صلاحیتیں ترقی کریں.
Page 181
غرض رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص برکات اور خاص رحمتیں لے کر آتا ہے.یوں تو اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کے دروازے ہر وقت ہی کھلے رہتے ہیں اور انسان جب چاہے ان سے حصہ لے سکتا ہے صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے ورنہ اس کی طرف سے دینے میں دیر نہیں لگتی کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کو کبھی نہیں چھوڑتا.ہاںبندہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بعض دفعہ دوسروں کے دروازہ پر چلا جاتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے بعد ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں اِدھر اُدھر پھر رہی تھی.اُسے جو بچہ بھی نظر آتا وہ اُسے اُٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیتی اور پیار کر کے چھوڑ دیتی.آخر اسی طرح تلاش کرتے کرتے اُسے اپنا بچہ مل گیا اور وہ اُسے لے کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ؓکو مخاطب کر کے فرمایا.اس عورت کو اپنا بچہ ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اللہ تعالیٰ کو اپنے گمشدہ بندہ کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے(مسلم کتاب التّوبة باب سعۃ رحمۃ اللہ تعالٰی و انھا تغلب غضبہ).سو اس رحیم و کریم ہستی سے تعلق پیدا کرنا کوئی مشکل امر نہیں.ہر گھڑی رمضان کی گھڑی ہو سکتی ہے اور ہر لمحہ قبولیت دُعا کا لمحہ بن سکتا ہے.اگر دیر ہوتی ہے تو بندہ کی طرف سے ہوتی ہے.لیکن یہ بھی اس کے احسانات میں سے ہی ہے کہ اس نے رمضان کا ایک مہینہ مقر ر کر دیا.تاکہ وہ لوگ جو خود نہیں اُٹھ سکتے ان کو ایک نظام کے ماتحت اُٹھنے کی عادت ہو جائے اور ان کی غفلتیں ان کی ہلاکت کا موجب نہ ہوں.پس یاد رکھو کہ روزے کوئی مصیبت نہیں ہیں.اگر یہ کوئی دکھ کی چیز ہوتی تو انسان کہہ سکتا تھا کہ میں دکھ میں کیوں پڑوں ؟ لیکن جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے روزے دکھوں سے بچانے اور گناہوں سے محفوظ رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی لِقاء حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں.اور گوبظاہر یہ ہلاکت کا باعث معلوم ہوتے ہیں.کیونکہ انسان فاقہ کرتا ہے.جاگتا ہے.بے وقت کھانا کھاتا ہے جس سے معدہ خراب ہوجاتا ہے اور پھر ساتھ ہی اس کے یہ احکام بھی ہیں کہ صدقہ و خیرات زیادہ کرو.اور غرباء کی پرورش کا خیال رکھو.مگر یہی قربانیاں ہیں جو اُسے خدا تعالیٰ کا محبوب بناتی ہیں.اور یہی قربانیاں ہیں جو قومی ترقی کا موجب بنتی ہیں.اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ١ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ (سو تم روزے رکھو ) چند گنتی کے دن.اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو (اسے) اور دنوں میں تعداد فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ١ؕ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ (پوری کرنی ) ہوگی.اور ان لوگوں پر جو اس کی (یعنی روزہ کی ) طاقت نہ رکھتے ہوں ایک مسکین کا کھا نا دینا(بطور
Page 182
طَعَامُ مِسْكِيْنٍ١ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ١ؕ وَ اَنْ فدیہ رمضان کے) واجب ہے.اور جو شخص پوری فرمانبرداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لئے بہتر ہوگا.تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۰۰۱۸۵ اور اگر تم علم رکھتے ہو تو( سمجھ سکتے ہو کہ)تمہارا روزے رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے.تفسیر.فرماتا ہے چند گنتی کے دن ہیں جن میں روزے رکھنا تم پر فرض کیا گیا ہے.ہاں جو تم میں سے بیمار یا مسافر ہو اس کے لئے اور دنوں میں اس تعداد کا پورا کرنا ضروری ہو گا.اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ اور فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ کے الفاظ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ یہ روزے جن کا حکم دیا جا رہا ہے نفلی نہیں بلکہ واجب ہیں.اسی لئے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار یا مسافر ہو تو اُسے بہرحال بعد میں اس تعداد کو پورا کرنا ہوگا.وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب رمضان کے دنوں میں مَیں بیمار تھا یا سفر پر گیا ہوا تھا تو اب رمضان کے بعد مَیں کیوں روزے رکھوں.جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ میں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر نہیں بلکہ صرف عام طور پر روزے رکھنے کا ذکر ہے وہ غلطی پر ہیں.اگر ان کی یہ بات صحیح ہو تو فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا.اول تو اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں صرف ایسے ہی روزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے لئے شریعت کی طرف سے بعض ایام مقرر ہیں.دوسرے اَيَّامٍ اُخَرَ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایام کسی خاص مہینہ سے متعلق ہیں.پس كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُسے عام نفلی روزے مراد لینا کسی طرح بھی درست نہیں ہو سکتا.پھر اس بارہ میں اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ جو شخص بیمار یا مسافر ہو اُسے بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے.بلکہ اَور دنوں میں اس کمی کو پورا کرنا چاہیے.میں نے اپنے تجربہ کی بنا پر یہ بات دیکھی ہے کہ رمضان کے بارہ میں مسلمانوں میں افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے.کئی تعلیم یافتہ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رمضان کی برکات کے قائل ہی نہیں اور بغیر کسی بیماری یا اور عذرِ شرعی کے روزہ کے تارک ہیں.اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سارااسلام روزہ میں ہی محدود سمجھتے ہیں.اور ہر بیمار، کمزور، بوڑھے، بچے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ ضرور روزہ رکھے خواہ بیماری بڑھ جائے یا صحت کو نقصان پہنچ جائے.یہ دونوں افراط و تفریط میں مبتلا ہیں.اسلام کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ وہ انسان کو اس راستہ سے ہٹا دے جو اس کی کامیابی کا ہے.
Page 183
اگر تو شریعت چٹّی ہوتی یا جرمانہ ہوتا تو پھر بے شک ہر شخص پر خواہ وہ کوئی بوجھ اُٹھا سکتا یانہ اٹھا سکتا اس کا اُٹھانا ضروری ہوتا.جیسے حکومت کی طرف سے جرمانہ کر دیا جائے تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس پر جرمانہ کیا گیا ہے اس میں ادا کرنے کی استطاعت بھی ہے یا نہیں بلکہ جس پر جرمانہ ہو اسے خواہ گھر بار بیچنا پڑے.بھوکا رہناپڑے جرمانہ کی رقم ادا کرنا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے.مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام چٹّی نہیں بلکہ وہ انسان کے اپنے فائدہ کے لئے ہیں.اور ان پر عمل کرنے سے خود انسان کو ہی آرام میّسر آتا اور اُس کی ترقی کے راستے کھلتے ہیں.جن مذاہب نے شریعت کو چٹّی قرار دیا ہے ان کے ماننے والوں کے لئے تو ضروری ہے کہ خواہ کچھ ہو وہ اپنے مذہبی احکام کو ضرور پورا کریں.لیکن جس مذہب کے احکام کی غرض محض انسانی فائدہ ہو اس میں نفع و نقصان کا موازنہ ہوتا ہے اور جو صورت زیادہ مفید ہو اسے اختیار کر لیا جاتا ہے.یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے بعض احکام کے سلسلہ میں بعض شرائط مقرر کر دی ہیں تاکہ اگر وہ شرائط کسی میں پائی جائیں تو وہ اس حکم پر عمل کرے اور اگر نہ پائی جائیں تو نہ کرے.یہ شرائط صرف جسمانی عبادت کے لئے ہی نہیں بلکہ مالی عبادت کے لئے بھی ہیں.جیسے زکوٰۃ ہے اور وطنی قربانی اور اتّصال و اتّحاد کی کوشش کے لئے بھی ہیں.جیسے حج ہے اسی طرح اور جتنے مسائل اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور جتنے احکام فرض ہیں ان سب کے لئے یہ شرط ہے کہ جب انسان کو طاقت ہو انہیں ضرور ادا کرے لیکن جب اس کی طاقت سے بات بڑھ جائے تو وہ معذور ہے اگر حج انسان کے مالدار ہونے اور امن و صحت کی شرط سے مشروط ہے.اگر زکوٰۃ کے لئے یہ شرط ہے کہ ایک خاص مقدار میں کسی کے پاس ایسا مال ہو جو اس کی ضروریات سے ایک سال بڑھا رہے.اگر نماز کے لئے یہ شرط ہے کہ جو کھڑا نہ ہو سکے بیٹھ کر اور جو بیٹھ نہ سکے لیٹ کر نماز ادا کرے تو رمضان کے لئے بھی یہ شرط ہے کہ اگرانسان مریض ہو.خواہ اسے مرض لاحق ہو چکا ہو یاا یسی حالت میں ہو جس میں روزہ رکھنا اسے یقینی طور پر مریض بنا سکتا ہو.جیسے حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا ایسا بوڑھا شخص ہے جس کے قویٰ میں انحطاط شروع ہو چکا ہے یا اتنا چھوٹا بچہ ہے جس کے قویٰ نشوونما پا رہے ہیں تو اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے.مسافر اوربیمار کا روزہ رکھنا ایسا ہی لغو ہے جیسے حائضہ کا روزہ رکھنا.کون نہیں جانتا کہ حائضہ کا روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں بلکہ بیوقوفی اور جہالت ہے.یہی حال بیمار اور مسافر کا ہے اس کے لئے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں.اسی طرح وہ بوڑھا جس کے قویٰ مضمحل ہو چکے ہوں اور روزہ اسے زندگی کے باقی اشغال سے محروم کر دیتا ہو اس کے لئے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں.پھر وہ بچہ جس کے قویٰ نشوونما پا رہے ہیں اور آئندہ پچاس ساٹھ سال کے لئے وہ طاقت کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کر رہا ہے اس کے لئے بھی روزہ رکھنا نیکی نہیں ہو سکتا مگر جس میں طاقت ہے اور جو رمضان کا صحیح معنوں میں مخاطب
Page 184
ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو گناہ کا مرتکب ہوتا ہے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے لیکن بلوغت کے قریب انہیں کچھ روزے رکھنے کی مشق ضرور کرانی چاہیے.مجھے جہاں تک یاد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھے پہلا روزہ رکھنے کی اجازت بارہ یا تیرہ سال کی عمر میں دی تھی.لیکن بعض بے وقوف چھ سات سال کے بچوں سے روزے رکھواتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ہو گا.یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ ظلم ہے.کیونکہ یہ عمر نشوونما کی ہوتی ہے.ہاں ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے دن قریب ہوتے ہیں اور روزہ فرض ہونے والا ہی ہوتا ہے اس وقت ان کو روزہ کی ضرور مشق کرانی چاہیے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت اور سنت کو اگر دیکھا جائے تو بارہ تیرہ سال کے قریب کچھ کچھ مشق کرانی چاہیے اور ہر سال چند روزے رکھوانے چاہئیں.یہاں تک کہ اٹھارہ سال کی عمر ہو جائے جو میرے نزدیک روزہ کی بلوغت کی عمر ہے.مجھے پہلے سال صرف ایک روزہ رکھنے کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجازت دی تھی.اس عمر میں تو صرف شوق ہوتا ہے.اس شوق کی وجہ سے بچے زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر یہ ماںباپ کا کام ہے کہ انہیں روکیں.پھر ایک عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں چاہیے کہ بچوں کو جرأت دلائیں کہ وہ کچھ روزے ضرور رکھیں.اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے رہیں کہ وہ زیادہ نہ رکھیں.اور دیکھنے والوں کو بھی اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے کہ یہ سارے روزے کیوں نہیں رکھتا کیونکہ اگر بچہ اس عمر میں سار ے روزے رکھے گا تو آئندہ نہیں رکھ سکے گا.اسی طرح بعض بچے خلقی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں.میں نے دیکھا ہے بعض لوگ اپنے بچوں کو میرے پاس ملاقات کے لئے لاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ اس کی عمر پندرہ سال ہے حالانکہ وہ دیکھنے میں سات آٹھ سال کے معلو م ہوتے ہیں.میں سمجھتا ہوں ایسے بچے روزہ کے لئے شاید اکیس سال کی عمر میں بالغ ہوں.اس کے مقابلہ میں ایک مضبوط بچہ غالباً پندرہ سال کی عمر میں ہی اٹھارہ سال کے برابر ہو سکتا ہے.لیکن اگر وہ میرے ان الفاظ ہی کو پکڑ کر بیٹھ جائے کہ روزہ کی بلوغت کی عمر اٹھارہ سال ہے تو نہ وہ مجھ پر ظلم کرےگا او رنہ خدا تعالیٰ پر بلکہ اپنی جان پر آپ ظلم کرے گا.اسی طرح اگر کوئی چھوٹی عمر کا بچہ پورے روزے نہ رکھے اور لوگ اس پر طعن کریں تو وہ اپنی جان پر ظلم کریںگے.بہرحال ان باتوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جہاں شریعت روکتی ہے وہاں رُک جانا چاہیے اور جہاں حکم دیتی ہے وہاں عمل کرنا چاہیے مگر مسلمان اس وقت اعتدال کو ترک کر بیٹھے ہیں ان میں یا تو وہ لوگ ہیں جو روزہ ہی نہیں رکھتے اور یا وہ لوگ ہیں جو روزہ کے ایسے پابند ہیں کہ بیماری اور سفر میں بھی اسے ضروری سمجھتے ہیں.
Page 185
اوربعض تو اس میں اس قدر شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں سے بھی روزے رکھواتے ہیں اور اگر وہ توڑنا چاہیں تو توڑنے نہیں دیتے.ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ سات سات آٹھ آٹھ سال کے بچوں نے روزے رکھے تو ماں باپ نے ان کی نگرانی کی کہ وہ روزہ توڑ نہ دیں یہاں تک کہ وہ مر گئے.بے شک روزہ کا ادب و احترام ان کے دلوں میں پیدا کرنا ضروری ہے اور انہیں بتانا چاہیے کہ اگر وہ سارا دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ رکھیں ہی نہیں.لیکن یہ کہ اگر وہ رکھ لیں تو پھر توڑیں نہیں خواہ مرنے لگیں نہایت ظالمانہ فعل ہے اور اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے.غرض ایک طرف تو مسلمانوں میں ایسے لو گ ہیں جو روزہ کے بارہ میں اس قدر سختی کرتے ہیں اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو روزوں کی ضرور ت ہی کے قائل نہیں بالخصوص تعلیم یافتہ طبقہ اسی خیال کا ہے.مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں میں نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ ایک شخص ٹرکی یا مصر سے یہاں آیا.وہ تقریریں کرتا پھرتا تھا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اس زمانہ میں ہوتے تو ضرور روزہ کی شکل بدل دیتے.اس لئے ہمیں بھی بدل دینی چاہیے کیونکہ وہ زمانہ اور تھا اور یہ اور ہے.اور اس کی صورت وہ یہ پیش کرتا تھا کہ روزہ کی حالت میں روٹی نہ کھائی جائے بلکہ صرف کچھ کیک اور بسکٹ وغیرہ کھا لئے جائیں.غرض ایک طبقہ افراط کی طرف چلا گیا ہے تو دوسرا تفریط کی طرف.حالانکہ اسلام ایک وسطی مذہب ہے او روہ جہاں بیمار اور مسافر کو اجازت دیتا ہے کہ وہ بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھیں وہاں ہر بالغ اور باصحت مسلمان پر یہ واجب قرار دیتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے اور ان مبارک ایام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح و تحمید اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعائوں اور ذکر الہٰی میں بسر کرے تاکہ اُسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو.بہر حال روزہ کے بارہ میں شریعت نے نہایت تاکید کی ہے.اور جہاں اس کے متعلق حد سے زیادہ تشدّد ناجائز ہے وہاں حد سے زیادہ نرمی بھی ناجائز ہے.پس نہ تو اتنی سختی کرنی چاہیے کہ جان تک چلی جائے اور نہ اتنی نرمی اختیار کرنی چاہیے کہ شریعت کے احکام کی ہتک ہو اور ذمہ داری کو بہانوں سے ٹال دیا جائے.میں نے دیکھا ہے کئی لوگ محض کمزوری کے بہانہ کی وجہ سے روزے نہیںرکھتے اور بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا جائے تو پیچش ہو جاتی ہے حالانکہ روزہ چھوڑنے کے لئے یہ کوئی کافی وجہ نہیں کہ پیچش ہو جایا کرتی ہے.جب تک پیچش نہ ہو انسان کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے.جب پیچش ہو جائے تو پھر بے شک چھوڑ دے.اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنے سے ضعف ہو جاتا ہے مگر یہ بھی کوئی دلیل نہیں.صرف اُس ضعف کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے
Page 186
جس میں ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرے.ورنہ یوں تو بعض لوگ ہمیشہ ہی کمزور رہتے ہیں تو کیا وہ کبھی بھی روزہ نہ رکھیں.میں اڑھائی تین سال کا تھا جب مجھے کالی کھانسی ہوئی تھی.اسی وقت سے میر ی صحت خراب ہے.اگر ایسے ضعف کو بہانہ بنانا جائز ہو تومیرے لئے تو شاید ساری عمر میں ایک روزہ بھی رکھنے کا موقع نہیں تھا.ضعف وغیرہ جسے روزہ چھوڑنے کا بہانا بنایا جاتا ہے اسی کی برداشت کی عادت ڈالنے کے لئے تو روزہ رکھایا جاتا ہے.یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ نماز بدی اور بے حیائی سے روکتی ہے.اس پر کوئی شخص کہے کہ میں نماز اس لئے نہیں پڑھتا کہ اس کی وجہ سے بدی کرنے سے رک جاتا ہوں.پس روزہ کی تو غرض ہی یہی ہے کہ کمزوری کو برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو ورنہ یوں تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس لئے روزہ نہیں رکھتا کہ مجھے بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے حالانکہ اس قسم کی تکالیف کی برداشت کی عادت پیدا کرنے ہی کے لئے روزہ مقرر کیا گیا ہے.جو شخص روزہ رکھے کیا وہ چاہتا ہے کہ فرشتے سارا دن اس کے پیٹ میں کباب ٹھونستے رہیں.وہ جب بھی روزہ رکھے گا اسے بھوک اور پیاس ضرور برداشت کرنی پڑے گی اور کچھ ضعف بھی ضرور ہو گا.اور اسی کمزوری اور ضعف کو برداشت کرنے کی عادت پیدا کرنے کے لئے روزہ رکھایا جاتا ہے.بے شک روزہ کی اور بھی حکمتیں ہیں جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے غرباء اور فاقہ زدہ لوگوں کی اعانت کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے مگر بہر حال روزہ اس لئے نہیں رکھا یاجاتا کہ انسان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور وہ کوئی ضعف محسوس نہ کرے بلکہ اس لئے رکھا یا جاتا ہے کہ اسے ضعف برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو.پس ضعف کے خوف سے روزہ چھوڑنا ہرگز جائز نہیں.سوائے اس کے کہ کوئی بوڑھا ہو چکا ہو یا ڈاکٹر اس کے ضعف کو بھی بیماری قرار دے چکا ہو.ایسی صورت میں بیشک روزہ نہیں رکھنا چاہیے مگر ضعف کے متعلق ظاہری ڈیل ڈول اور صورت سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے.بعض لوگ بظاہر موٹے تازے ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے بھی ہیں.لیکن دراصل وہ بیمارہوتے ہیں اور ان کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا.بالخصوص جن لوگوں کو دل کی بیماری ہو.ایسے لوگوں کے لئے بھوک پیاس کا برداشت کرنا سخت خطرناک ہوتا ہے پس کمزوری یا ضعف کا فیصلہ بظاہر دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ دیکھنا ہو گا کہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے.مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے ڈاکٹر بھی دیانت داری سے کام نہیں لیتے.ذرا کوئی شخص دو چار بار جھک کر سلام کر دے تو جو چاہے ڈاکٹر سے لکھوالے ظاہر ہے کہ ایسے سرٹیفیکیٹ کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر حقیقی طور پر ڈاکٹر کسی کو مشورہ دے کہ اس کے لئے روزہ رکھنا مضر ہے تو گو وہ بظاہر تندرست بھی نظر آئے اس کے لئے روزہ رکھنا جائز نہیں ہو گا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ بیمار اور مسافر کے لئے روزہ جائز نہیں.
Page 187
چنانچہ آپؑ نے ایک دفعہ فرمایا.’’جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہِ صیام میں روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ بیمار اور مسافر روزہ نہ رکھے.مرض سے صحت پا نے اور سفرکے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے.خدا کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ نجات فضل سے ہے نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے.خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے.مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئےگا.‘‘ (فقہ المسیح صفحہ۲۱۰ بحوالہ بدر ۱۷؍ اکتوبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۷ ) پھر فرماتا ہے وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ.اس آیت کی تفسیر میں مفسّرین کو بڑی دقّت پیش آئی ہے اور انہوں نے اس کے کئی معنے کئے ہیں.یہ دقت زیادہ تر اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ يُطِيْقُوْنَهٗ میں جو ہٗ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اس کے مرجع کی تعیین میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض نے اس کا مرجع صوم کو قرار دیا ہے اور بعض نے فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ کو.شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مشکل کو ’’الفوز الکبیر‘‘ میں اس طرح حل کیا ہے کہ يُطِيْقُوْنَهٗ میں ہٗ کی ضمیر فِدْیَۃٌ طَعَامُ مِسْکِیْنٍ کی طرف گئی ہے اس پر یہ اعتراض پڑتا تھا کہ یہ اضمار قبل الذکر ہے یعنی ضمیر پہلے آ گئی ہے اور مرجع بعد میں ہے.حالانکہ مرجع پہلے ہونا چاہیے تھا اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ فدیہ کا مقام چونکہ نحواً مقدم ہے یعنی وہ مبتدا ہے اس لئے اس کی ضمیر اس کے ذکر سے پہلے آسکتی ہے.دوسرا اعتراض یہ پڑتا تھا کہ فِدْیَۃٌ مؤنث ہے اور ضمیر مذکر.اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ فدیہ طَعَامُ مِسْکِیْنٍ کا قائم مقام ہے اور وہ مذکر ہے.اس لئے فدیہ کی طرف بھی مذکر کی ضمیر پھر سکتی ہے.اس بنا پر انہوں نے اس کے یہ معنے کئے ہیں کہ ان لوگوں پر جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دینا واجب ہے.ان کے نزدیک اس آیت میں صدقۃ الفطر کی طرف اشارہ ہے جو اسلام میں نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ غرباء بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکیں.دوسرے معنے اس کے یہ کئے جاتے ہیں کہ مومنوں میں سے جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزوں کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ بھی دے دیا کریں(قرطبی).لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور احادیث سے چونکہ یہ بات ثابت نہیں کہ روزہ دار فدیہ بھی دے اس لئے یہ معنے تسلیم نہیں کئے جا سکتے.اس کے علاوہ
Page 188
عقلی طور پر یہ معنے اس لئے بھی نا قابلِ قبول ہیں کہ فدیہ تو اس پر ہونا چاہیے جو روز ہ نہ رکھ سکے جو شخص باقاعدہ روزے رکھ رہا ہے اس پر فدیہ کیسا؟ ہاں اگر کوئی شخص اس شکریہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عبادت کے بجا لانے کی توفیق بخشی ہے روزہ رکھ کر ایک مسکین کو کھانا بھی دے دیا کرے تو وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے کیونکہ اس نے روزہ بھی رکھا اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا.مگر بہرحال وہ ایک زائد نیکی ہو گی.قرآن کریم کسی کو اس بات کا پابند قرار نہیں دیتا کہ وہ روزہ بھی رکھے او رایک مسکین کوکھانا بطور فدیہ بھی کھلائے.(۳)مفسّرین نے اس آیت کے ایک معنے یہ کئے ہیں کہيُطِيْقُوْنَهٗ سے پہلے لَا محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے کہ وَعَلَی الَّذِیْنَ لَا یُطِیْقُوْنَہٗ.اور ہٗ کی ضمیر کا مرجع وہ صوم کو قرار دیتے ہیں(بحر محیط زیر آیت ھذا) یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے دیا کریں.وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ لَا اُسی طر ح محذوف ہے جس طرح آیت یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمْ اَنْ تَضِلُّوْا (النساء: ۱۷۷) میں تَضِلُّوْا سے پہلے بھی لَا محذوف ہے ا ور آیت کے معنے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں اس لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جائو.گو یہ بھی کہاجا سکتا ہے کہ یہاں لَا مقدر نہیں بلکہ ایک مضاف محذوف ہے اور اصل عبار ت یوں ہے کہ یُبَیِّنُ اللّٰہُ لَکُمْ مَّخَافَۃَ اَنْ تَضِلُّوْا یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لئے یہ باتیں تمہارے گمراہ ہو جانے کے خدشہ کی بنا ء پر بیان کرتا ہے.(۴) بعض نے اس آیت کا یوں حل کیا ہے کہ عربی زبان میں اَطَاقَ کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ کسی شخص نے کام تو کیا مگر بہت مشکل اور مصیبت سے.(بحر محیط زیر آیت ھذا) گویا جب کوئی شخص اپنے نفس کو انتہائی مشقّت میں ڈالے بغیر کوئی کام سر انجام دینے کی اپنے اندر طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے اَطَاقَ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے.اس مفہوم کے لحاظ سے اَلَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ سے وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ سے سخت تکلیف اٹھاتے ہیں اور جن کی بدنی طاقت بالکل زائل ہو جاتی ہے بلکہ بعض دفعہ غشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے جیسے بوڑھے یا دل کے مریض یا اعصابی کمزوری کے شکار یا حاملہ اور مرضعہ.ایسے لوگ جو بظاہر تو بیمار نظر نہیں آتے لیکن روزہ رکھنے سے بیمار ہو جاتے ہیں ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے رکھنے کی بجائے ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ اپنی طرف سے دےدیا کریں.ان معنوں کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ علامہ قرطبی نے یُطِیْقُوْنَ کی ایک قراء ت یُطَوِّ قُوْنَ بھی بیان کی ہے.یعنی جو لوگ صرف مشقت سے روزہ نبھا سکتے ہیں.اور جن کی صحت روزہ رکھنے سے غیر معمولی طور پر خراب ہو جاتی ہے وہ بیشک روزے نہ رکھیں ہاں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دےدیا کریں.
Page 189
میرے نزدیک چونکہ اَطَاقَ بابِ اِفعال میں سے ہے اور بابِ افعال کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ سلب کے معنے دیتا ہے اس لئے وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ کے یہ معنے ہوںگے کہ وہ لوگ جن کی طاقت کمزور ہو گئی ہے یعنی قریباً ضائع ہو گئی ہے وہ بیشک روزہ نہ رکھیں مگر چونکہ ان کا روزہ نہ رکھنا محض اجتہادی امر ہو گا مرض ظاہر کے نتیجہ میں نہیں ہوگا بلکہ صرف متوقع کمزوری کے نتیجہ میں ہو گا.اور اجتہاد میںغلطی بھی ہو سکتی ہے اس لئے ان کو چاہیے کہ اپنی اجتہادی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لئے اگر ان کو فدیہ دینے کی طاقت ہو تو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ان دنوں میں دے دیا کریں تاکہ ان کی غلطی کے امکان کا کفارہ ادا ہوتا رہے.(۵) ایک اور معنے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھ پر کھولے ہیں وہ یہ ہیں کہ يُطِيْقُوْنَهٗ میں ہٗ کی ضمیر روزہ کی طرف پھرتی ہے اور مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی بیماری شدید ہے یا جن کا سفر پُر مشقت ہے وہ تو بہرحال فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ کے مطابق دوسرے ایام میں روزے رکھیں گے.لیکن وہ لوگ جو کسی معمولی مرض میں مبتلا ہیں یا کسی آسانی سے طے ہونے والے سفر پر نکلے ہیں اگر وہ طاقت رکھتے ہوں تو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ بھی دے دیا کریں.اس وجہ سے کہ ممکن ہے انہوں نے روزہ چھوڑنے میں غلطی کی ہو.وہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بیماری ایسی نہ ہو کہ وہ روزہ ترک کر سکیں.یا وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا سفر سفر ہی نہ سمجھا گیا ہو.پس چونکہ ان کی رائے میں غلطی کا ہر وقت امکان ہے اس لئے ایسے بیماروں اور مسافروں کو چاہیے کہ ان میں سے جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہوں وہ دوسرے ایام میں فوت شدہ روزوں کو پورا کرنے کے علاوہ ایک مسکین کو کھانا بھی دے دیا کریں.تاکہ ان کی اس غلطی کا کفارہ ہو جائے.اور اگر يُطِيْقُوْنَهٗ میں ہٗ کی ضمیر کا مرجع فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ کو ہی قرار دیا جائے.جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے لکھا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ اس حکم کو صدقۃ الفطر پر محمول کیا جائے.اس آیت کا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَسے تعلق ہو گا اور اس کے یہ معنے ہوںگے کہ اگرچہ مریض اور مسافر کو یہ اجازت ہے کہ وہ اَور دنوں میں روزہ رکھ لیں لیکن ان میں سے وہ لوگ جن کو آسودگی حاصل ہو اور وہ ایک شخص کو کھانا کھلا سکتے ہوں انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ رمضان دے دیا کریں.اگر طاقت نہ ہو تو پھر تو فدیہ رمضان دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.لیکن اگر طاقت ہو تو خواہ وہ بیمار ہوں یا مسافر انہیں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ رمضان دینا چاہیے.اگر روک عارضی ہو اور وہ بعد میں دور ہو جائے تو روزہ تو بہر حال رکھنا ہو گا.فدیہ دےدینے سے روزہ اپنی ذات میں ساقط نہیں ہو جاتا بلکہ یہ محض اس بات کا فدیہ ہے کہ ان مبارک ایام میں وہ کسی جائز شرعی عذر کی بنا پر باقی
Page 190
مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ عبادت ادا نہیں کر سکے.آگے یہ عذر دو قسم کے ہوتے ہیں ایک عارضی اور ایک مستقل.فدیہ بشرطِ استطاعت ان دونوں حالتوں میں دینا چاہیے.پھر جب عذر دور ہو جائے تو روزہ بھی رکھنا چاہیے.غرضیکہ خواہ کوئی فدیہ بھی دے دے.بہرحال سال دو سال یا تین سال کے بعد جب بھی اس کی صحت اجازت دے اسے پھر روزے رکھنے ہوںگے سوائے اس صورت کے کہ پہلے مرض عارضی تھا اور صحت ہونے کے بعد وہ ارادہ ہی کرتا رہا کہ آج رکھتا ہوں کل رکھتا ہوں کہ اس دوران میں اس کی صحت پھر مستقل طور پر خراب ہو جائے.باقی جو بھی کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہو اگر وہ مریض یا مسافر ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ رمضان میں ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دے اور دوسرے ایام میں روزے رکھے یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ و السلام کا مذہب تھا اور آپ ہمیشہ فدیہ بھی دیتے تھے اور بعد میں روزے بھی رکھتے تھے اور اسی کی دوسروں کو تاکید فرمایا کرتے تھے.اس آیت میں جو اَلَّذِیْنَ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ دو کا بدل یعنی قائم مقام ہو سکتا ہے.اوّل ان مومنوں کا جن کا ذکر يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ میں کیا گیا ہے.دوم اُن لوگوں کا جن کا ذکر فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ میں ہے.اگر اسے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کا بدل سمجھا جائے تو اس آیت کے یہ معنے ہوںگے کہ وہ لوگ جو ضعف کی وجہ سے روزے سے سخت تکلیف اُٹھاتے ہیں اور اپنے نفس پر بڑی مشقّت برداشت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کی بجائے ایک مسکین کا کھانا بطورفدیہ دے دیا کریں.اور اگر دوسرا بدل لیں تو اس کے یہ معنی ہوںگے کہ وہ مریض اور مسافر جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں اور پھر دوسرے دنوں میں روزے بھی رکھیں.کیونکہ بعض امراض ایسی ہوتی ہیں یا بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ آیا اس میں روزہ ترک کیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟ حدیث میں آیا ہے کہ مشکوک اشیاء بھی محارم ہی کے نیچے ہوتی ہیں کیونکہ جو مشکوک تک پہنچتا ہے وہ آہستہ آہستہ محارم تک بھی پہنچ جاتا ہے(بخاری کتاب البیوع باب الحلال بیّن و الحرام بیّن و بینھما مشتبھات).پس اگر یہ دونوں باتیں مشکوک ہوں تو ایسے مسافر اورمریض کو چاہیے کہ فدیہ دے دے اور رخصت سے فائدہ اٹھائے اور بعد میں روزے بھی رکھ لے.اس میں ایسی بیماری والا جس کی بیماری مشتبہ ہو یا ایسا سفر والا جس کا سفر مشتبہ ہو مراد ہیں.ان میں سے جو لوگ طاقت رکھتے ہوں اُن پر فدیہ دینا لازم ہے کیونکہ ممکن ہے انہوں نے اپنے اجتہاد میں غلطی کی ہو.اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہی مذہب تھا کہ ایسے لوگ دوسرے ایام میں روزہ رکھیں.اور رمضان کے دنوں میں فدیہ دیں.پھر فرماتا ہے فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ جو شخص پوری بشاشت اور شوق کے ساتھ نیکی کا کوئی کام کرتا ہے
Page 191
تو خواہ وہ ابتداء میں تکلّف کے ساتھ ہی ایسا کرے اور اسے اپنے نفس پر ایک رنگ میں بوجھ ہی محسوس ہو تب بھی اس کا نتیجہ اس کے لئے اچھا نکلے گا.یعنی وہ نیکی اس کے لئے بہترین نتائج پیدا کرنے والی ثابت ہو گی.عربی زبان میں تَطَوُّع کا لفظ اُس وقت استعمال ہوتا ہے جب اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر کسی حکم کی اطاعت کی جائے.اور تکلّف سے بشاشت کا اظہار کیا جائے (مفردات).پس فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو شخص پورے شرح صدر کے ساتھ کسی نیکی میں حصہ نہ لے سکے اُسے چاہیے کہ کم از کم اپنے نفس پر بوجھ ڈالتے ہوئے ہی اس میں حصہ لے اور اپنے چہرہ پر تکلّف سے بشاشت پیداکرے اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس کیلئے خیر اوربرکت کے رستے کھول دےگا.یعنی نیکیوں میں ترقی کرتے کرتے اُسے ایسا مقام میسّر آجائےگا کہ نیکی اس کی غذابن جائےگی اور نیک تحریکات پر عمل اس کےلئے ایسا ہی آسان ہو جائےگا جیسے اعلیٰ درجہ کے مومنوں کےلئے آسان ہوتاہے.لیکن اس کے علاوہ تَطَوُّع کے معنے محاورہ میں غیر واجب کا م کے نفلی طور پر کرنے کے بھی ہوتے ہیں.اور امام راغب نے اپنی مشہور کتاب مفردات میں اس کی تصریح کی ہے.اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنے ہوںگے.کہ جو شخص نفلی طور پر کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کےلئے بہت بہتر ہو گا.یعنی رمضان میں روزے رکھنے یا ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم تو ہم نے دے دیا ہے لیکن اگر کوئی شخص ثواب کی نیت سے اس میں کوئی زیادتی کرنا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہے.مثلاً وہ اختیار رکھتا ہے کہ ایک کی بجائے دو مساکین کا کھانا بطور فدیہ دے دے.یا وہ اختیار رکھتا ہے کہ روزہ بھی رکھے اور حصول ثواب کےلئے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلاتا رہے.یا رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی طور پر دوسرے ایام میں بھی روزے رکھے.یہ سب حصول ثواب کے ذرائع ہیںجن میں ہر مومن اپنی اپنی طاقت کے مطابق حصہ لے کراللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے.پھر فرمایا وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ.اس کے بعض لوگ یہ معنے کرتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے.مگر یہ صحیح نہیں.اگر یہ معنے ہوتے تو اِنْ تَصُوْمُوْاکہناچاہیے تھا.نہ کہ اَنْ تَصُوْمُوْا.اس کے صحیح معنے یہ ہیں کہ اگر تم علم رکھتے ہوتو سمجھ سکتے ہو کہ روزہ رکھنا تمہارے لئے بہر حال بہتر ہے.یعنی ہم نے جس حکم کےلئے یہ تمہید اُٹھائی ہے.وہ کوئی معمولی حکم نہیں بلکہ ایک غیر معمولی خیر اور برکت رکھنے والا حکم ہے.اس لئے تمہارا فرض ہے کہ تم اسے پوری توجہ سے سُنو اور اس پر عمل کرو.
Page 192
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ رمضان کا مہینہ وہ (مہینہ) ہے جس کے بارہ میں قرآن(کریم) نازل کیا گیا ہے.(وہ قرآن)جو تمام انسانوں بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ١ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ کےلئے ہدایت (بنا کر بھیجاگیا) ہے اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے(ایسے دلائل) جو ہدایت پیدا کرتے ہیں الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ١ؕ وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اور اس کے ساتھ ہی (قرآن میں) الٰہی نشانات بھی ہیں.اس لئے تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو (اس حال میں) فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ١ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا دیکھے (کہ نہ مریض ہو نہ مسافر) اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے.جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تواس پر يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ١ٞ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى اور دنوں میں تعداد (پوری کرنی واجب )ہوگی.اللہ(تعالیٰ ) تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لئے تنگی مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۰۰۱۸۶ نہیں چاہتا (یہ حکم اس نے اس لئے دیا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو) اور تاکہ تم تعداد کو پورا کر لو.اور اس (بات)پر اللہ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے اور تاکہ تم (اس کے ) شکر گذار بنو.حل لغات.ھُدًی یہ مصدر ہے اور فاعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے.یعنی لوگوں کو ہدایت دینے والا.مزید تشریح کے لئے دیکھیں سورۃ بقرۃ آیت نمبر ۱۷۹ جلد ھذا.بَیِّنَاتٍ جمع ہے اس کا مفرد اَلْبَیِّنَۃُ ہے.جس کے معنے ہیں اَلدِّلَالَۃُ الْوَاضِحَۃُ عَقَلِیَّۃً کَانَتْ اَوْ مَحْسُوْسَۃً یعنی واضح دلیل خواہ وہ عقلی ہو یا حِس سے تعلق رکھتی ہو.(مفردات) تفسیر.رمضان کا مہینہ ان مقدس ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم جیسی کامل کتاب کا دنیا میں نزول ہوا.وہ مبارک دن.وہ دنیا کی سعادت کی ابتداء کے دن.وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اُس کی برکت کے
Page 193
دروازے کھولنے والے دن جب دنیا کی گھنائونی شکل اس کے بد صورت چہرے اور اس کے اذیت پہنچانے والے اعمال سے تنگ آکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر اور دنیا سے منہ موڑ کر اور اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر صرف اپنے خدا کی یاد میں مصروف رہا کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ دنیا سے اس طرح بھاگ کر وہ اپنے فرض کو ادا کریںگے جسے ادا کرنے کےلئے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے.انہی تنہائی کی گھڑیوں میں انہی جدائی کے اوقات میں اور انہی غور وفکر کی ساعات میں رمضان کا مہینہ آپ پر آگیا.اور جہاں تک معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے چوبیسویں رمضان کو وہ جو دنیا کو چھوڑ کر علیحدگی میں چلا گیا تھا اسے اس کے پیدا کرنے والے اُس کی تربیت کرنے والے، اُس کو تعلیم دینے والے اور اس سے محبت کرنے والے خدا نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ.اور بتایا کہ تم مجھے تنہائی میں اور غار حرا میں ڈھونڈتے ہو مگر میں تمہیں مکہ کی گلیوں اور ان کے شوروشغب میں ملوں گا.جاؤ اور اپنی قوم کو پیغام پہنچا دو کہ میں نے تم کو ادنیٰ حالت میں پیدا کر کے اور پھر ترقی دے کر اس لئے دنیا میں نہیں بھیجا کہ کھاؤ پیؤ اور مر جاؤ اور کوئی سوال تم سے نہ کیا جائے.آپ اس آواز کو سن کر حیران رہ گئے.آپ نے جبرائیل کو حیرت سے دیکھ کر کہا کہ مَااَنَا بِقَارِیئٍ.(بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی) میں تو پڑھنا نہیں جانتا.یعنی اس قسم کا پیغام مجھے عجیب معلوم ہوتا ہے.کیا یہ الفاظ میرے منہ سے مکہ والوں کے سامنے زیب دیںگے ؟ کیا میری قوم ان کو قبول کرے گی اور سُنے گی؟ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو متواتر حکم دیا گیا کہ جاؤ اور پڑھو.جاؤاور پڑھو.جاؤاور پڑھو.تب آپ نے اس آواز پر اس ارشاد کی تعمیل میں تنہائی کو چھوڑا اور جلوت اختیار کی.مگر وہ کیسی مجلس تھی.وہ ایسی نہ تھی کہ جس میں ایک دوست بیٹھ کر دوسرے دوست کے سامنے اپنے شکوے بیان کرتا ہے ،وہ ایسی مجلس نہ تھی جس میں دوست اپنے دوست کے خوش کر نے والے حالات سنتا اور اس سے لطف اٹھاتا ہے ، وہ ایسی مجلس نہ تھی جس میں انسان اپنی ذہنی کوفت اور تھکان دُور کرتا ہے.وہ قصوں اورکہانیوں والی مجلس نہ تھی،شعروشاعری کی مجلس نہ تھی.وہ ایسی مجلس نہ تھی جس میں مباحثات اور مناظرات ہوتے ہیں.بلکہ وہ مجلس ایسی تھی جس میں ایک طرف سے متواتر اور پیہم اخلاص کا اظہار ہوتا تھا تو دوسری طرف سے متواتر اور پیہم گالیاں، دُشنام،ڈراوے اور دھمکیاں ملتی تھیں.وہ ایسی مجلس تھی جس میں ایک دفعہ جانے کے بعد دوسرے دن جانے کی خواہش باقی نہیں رہتی.وہ ایسی گالیاں اور ایسے ارادے اور ایسی دھمکیاں ہوتی تھیں کہ ایک طرف اُن کے دینے والے سمجھتے تھے کہ اگر اس شخص میں کوئی حِس باقی ہے تو کل اس کے منہ سے ایسی بات ہرگز نہیں نکلے گی.وہ خوش ہوتے تھے کہ آج ہم نے محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بند کر
Page 194
دی اوردوسری طرف جب خدا تعالیٰ کا سورج چڑھتا تو خدا تعالیٰ کا یہ عاشق صادق خدا تعالیٰ کا پیغام مکہ والوں کو پہنچانے کے لئے پھر نکل کھڑا ہوتا.پھر تمام دن وہی گالیاں وہی دھمکیاں اور وہی ڈراوے ہوتے تھے اور اسی میں شام ہو جاتی.مگر جب رات کا پردہ حائل ہوتا تو وہ سمجھتے کہ شاید آج یہ خاموش ہو گیا ہو گا.مگر وہ جس کے کانوں میں خدائی آواز گونج رہی تھی.وہ مکہ والوں سے دب کر کیسے خاموش ہو جاتا؟اگر تو اس کی رات سوتے گزرتی توبے شک اس پیغام کو بھول جاتا مگر جب اُس کے سونے کی حالت جاگنے ہی کی ہوتی تو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟وہ سبق جو دوہرایا نہ جائے بیشک بھول سکتا ہے مگر جب آپ کی یہ حالت تھی کہ جو نہی سرہانے پر سر رکھا وہی اِقْرَئْ کی آواز آنی شروع ہو جاتی تو آپ کس طرح اس پیغام کو بھول جاتے؟ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو رمضان ہی میں یہ آواز آئی اور رمضان ہی میں آپ نے غار حرا سے باہر نکل کر لوگوں کو یہ تعلیم سنانی شروع کی.اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اُترا.دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّآ اَنْزَلْنٰہُ فِیْ لَیْلَۃِ الْقَدْرِ وَمَآ اَدْرٰکَ مَا لَیْلَۃُ الْقَدْرِ.(القدر:۲،۳)یعنی قرآن لیلۃ القدر میں اُتارا گیا ہے.رَمَضَان رَمَض سے نکلا ہے.جس کے معنے عربی زبان میں جلن اور سوزش کے ہیں (اقرب).خواہ وہ جلن دھوپ کی ہو خواہ بیماری کی.اس لئے رَمَضَان کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا موسم جس میں سختی کے اوقات اور ایام ہوں.اور اِدھر فرمایا.ہم نے اسے رات کو اتارا ہے اور رات تاریکی اور مصیبت پر دلالت کرتی ہے.پس ان دونوں آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے.کہ الہام کا نزول تکالیف اور مصائب کے ایام میں ہوا کرتاہے.جب تک کوئی قوم مصائب اور شدائد سے دوچار نہیں ہوتی ،جب تک اُس کے دن راتیں نہیں بن جاتے ،جب تک وہ بھوک اور پیاس کی شدّت سے تکلیف نہیں اُٹھاتی، جب تک انسانی جسم اندر اور باہر سے مصیبت نہیں اٹھاتا اُس وقت تک خدا تعالیٰ کا کلام اُس پر نازل نہیں ہوسکتا.اور اس ماہ کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی بتایا ہے کہ اگر تم اپنے اوپر الہام الٰہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تکالیف اور مصائب میں سے گذرو اِس کے بغیر الہام الٰہی کی نعمت تمہیں میسّر نہیں آسکتی.پس رمضان کلام الٰہی کو یاد کرانے کا مہینہ ہے.اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے اور اسی وجہ سے ہم بھی اس مہینہ میں درسِ قرآن کا انتظام کرتے ہیں.دوستوں کو چاہیے کہ اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کے معانی پر غور کیا کریں تاکہ اُن کے اندر قربانی کی روح پیدا ہو جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی.بہر حال یہ مہینہ بتاتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا فتح کرے اُس کےلئے ضروری ہے کہ وہ غار حرا کی علیحدگیوں میں جائے.دنیا چھوڑے
Page 195
بغیر نہیں مل سکتی.پہلے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ضروری ہوتی ہے اور پھر وہ قبضہ میں آتی ہے مگر وہ قبضہ جسے الٰہی قبضہ و تصّرف کہتے ہیں.ایک دنیوی قبضہ ہوتا ہے جیسے د ّجال کا ہے.اس کے ملنے کا بیشک یہی طریق ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کےلئے وقف کر دیا جائے لیکن جو شخص خدا تعالیٰ کا ہو کر اس پر قبضہ کرنا چاہے وہ اُسی صورت میں کر سکے گا جب اُسے چھوڑ دےگا.دیکھو ابوجہل نے دنیا کےلئے کوشش کی اور اُسے حاصل کیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے چھوڑدیا اور پھر بھی وہ آپ کومل گئی.بلکہ ابو جہل سے زیادہ ملی.ابوجہل زیادہ سے زیادہ مکہ کا ایک رئیس تھا مگر آپ اپنی زندگی میں ہی سارے عرب کے بادشاہ ہو گئے اور آج ساری دنیا کے شہنشاہ ہیں.غرض جو دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ ابو جہل کو کہاں حاصل ہوئی؟ مگر ابو جہل کو جو کچھ حاصل ہوا وہ دنیا کمانے سے ملا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا وہ دنیا چھوڑنے سے ملا.پس روحانی جماعتوں کو دنیا چھوڑ دینے سے ملتی ہے.اور دنیوی لوگوں کو دنیا کمانے سے ملتی ہے.اور رمضان ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اگر تم اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ پہلے شدائد اور مصائب قبول کرو.راتوں کی تاریکیاں قبول کرو اور ان چیزوں سے مت گھبراو ٔ.کیونکہ یہی قربانیاں تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہیں.غرض رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے.اور جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہوتی ہے وہ اس مہینہ کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص قسم کی کپکپاہٹ محسوس کئے بغیر نہیں رہ سکتا.کتنی ہی صدیاں ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گذر جائیں، کتنے ہی سال ہمیں اور انکو آپس میں ُجدا کرتے چلے جائیں کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں حائل ہو تا چلا جائے لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں معلوم ہوتاہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینہ نے لپیٹ لپاٹ کر چھوٹا سا کر کے رکھ دیا ہے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قریب نہیں چونکہ قرآن خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس لئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلہ کو رمضان نے سمیٹ سماٹ کر ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے.وہ بُعد جو ایک انسان کو خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، وہ بُعد جو ایک مخلوق کو اپنے خالق سے ہوتا ہے.وہ بُعد جو ایک کمزور اور نالائق ہستی کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا سے ہوتا ہے وہ یوں سمٹ جاتا ہے وہ یوں مٹ جاتا ہے وہ یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے سورج کی کرنوں سے رات کا اندھیرا.یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے.اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ (البقرۃ:۱۸۷).جب رمضان کا مہینہ آئےاور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں کہ میں انہیں کس
Page 196
طرح مل سکتا ہوں تو تُو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور خدا تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں.یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کےلئے ظاہر ہوا.اور اُس نے چاہا کہ پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے.اس کلام کے ذریعہ جو حبل اللہ ہے.جو خدا کا وہ ر ّسہ ہے جس کا ایک سِرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس ر ّسہ پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں.اب میں بتاتا ہوں کہ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ کے تین معنے ہو سکتے ہیں.اوّل اس جگہ فی تعلیلیہ ہے اور آیت کے معنے یہ ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے بارہ میں قرآن کریم اتارا گیا ہے.یعنی رمضان المبارک کے روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ ان کے بارہ میں قرآن کریم میں خاص طور پر احکام نازل کئے گئے ہیں.اور جس حکم کے بارہ میں قرآنی وحی نازل ہو اُس کے متعلق ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کتنا اہم اور ضروری ہو گا.فِیْکے یہ معنے لغت سے بھی ثابت ہیں.چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں تَکلَّمْتُ مَعَکَ فِیْ ھٰذَالْاَ مْرِ میں نے تجھ سے اس امر کے متعلق گفتگو کی.اسی طرح قرآن کریم میں بھی اس کی مثال پائی جاتی ہے.سورۃ یوسف میں اِمْرَ أۃُ الْعَزِیْز کے متعلق آتا ہے کہ اُس نے کہا فَذٰلِکُنَّ الَّذِیْ لُمْتُنَّنِیْ فِیْہِ (یوسف :۳۳) یہ وہ شخص ہے جس کے بارہ میں تم نے مجھے ملامت کی ہے.اسی طرح حدیث میں آتاہے عُذِّبَتْ اِمْرَأَ ۃٌ فِیْ ھِرَّۃٍ حَبَسَتْھَا( بخاری کتاب المساقاۃ باب فضل سقی الماء) ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کیونکہ اُس نے اُسے بغیر کھلائے پلائے باندھ دیا تھا یہاں تک کہ وہ مر گئی.دوسرے معنے یہ ہیں کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا.چنانچہ حدیثوں سے صاف طور پر ثابت ہے کہ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینہ میں شروع ہوا.اور گو تاریخ کی تعیین میں اختلاف ہے لیکن محدثین عام طورپر ۲۴ تاریخ کی روایت کو مقدم بتاتے ہیں.چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ زرقانی دونوں نے اس روایت کو ترجیح دی ہے کہ قرآن کریم رمضان کی ۲۴ تاریخ کو اُترنا شروع ہوا تھا.تیسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ رمضان میں پورا قرآن اتارا گیا.جیسے احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا أَنَّ جِبْرِیْلَ کَانَ یُعَارِضُنِیَ الْقُرْاٰنَ فِیْ کُلَّ سَنَۃٍ مَرَّۃً وَ اِنَّہٗ عَارَ ضَنِیَ الْعَامَ مَرَّ تَیْنِ یعنی جبریل ہر سال رمضان کے مہینہ میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دفعہ دَور کیا کرتے تھے.مگر اس سال انہوں نے دو دفعہ دَور کیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے (شرح العلامۃ الزرقانی علی المواھب اللدنیۃ الفصل
Page 197
الاول فی اتمامہ تعالیٰ نعمتہ علیہ بوفاتہ...)اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی قرآن نازل ہوا ہے مگر رمضان المبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جس حد تک قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا تھا جبریل اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دَور کیا کرتے تھے.گویا دوسرے الفاظ میں دوبارہ تمام قرآن کریم آپ پر نازل کیا جاتا.بخاری کتاب بدء الوحی میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے.چنانچہ حضرت ابنِ عباسؓ سے روایت ہے کہ کَانَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَجْوَدَ النَّاسِ وَکَانَ اَجْوَدُ مَایَکُوْنُ فِیْ رَمَضَانَ حِیْنَ یَلْقَاہُ جِبْرِیْلُ وَکَانَ یَلْقَاہُ فِیْ کُلِّ لَیْلَۃٍ مِنْ رَمَضَانَ فَیُدَ ارِسُہُ الْقُرْاٰنَ فَلَرَسُوْلُ اللّٰہِ (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ) اَجْوَدُ بِالْخَیْرِ مِنَ الرِّیْحِ الْمُرْسَلَۃِ.( بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی)یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے اور زیادہ ترسخاوت آپ رمضان میں فرمایا کرتے تھے جبکہ جبریل آپ سے ملتے تھے.اور جبریل رمضان کے مہینہ میں ہررات آپ سے ملا کرتے تھے اور تمام قرآن کریم کا آپ کے ساتھ مل کر دَور کیا کرتے تھے.اُن دنوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارش لانے والی ہوا سے بھی اپنے جود وکرم میں بڑھ جاتے تھے.ان حوالجات سے ثابت ہے کہ ابتدائے نزولِ قرآن بھی رمضان کے مہینہ میںہوا اور پھر ہر رمضان میں جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا جبریل دوبارہ نازل ہو کر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖ وسلم کے ساتھ مل کر دوہراتے تھے.اس روایت کو مدِّنظر رکھ کر کہا جاسکتا ہے کہ سارا قرآن کریم ہی رمضان میں نازل ہوا.بلکہ کئی حصے متعدد بار نازل ہوئے یہاں تک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اگر ۲۳ رمضان آئے تو بعض آیات ایسی تھیں جو ۲۳ بار نازل ہوئیں بعض ۲۲ بار نازل ہوئیں.بعض ۲۱ بار اور بعض ۲۰ بار.اسی طرح جو آیات آخری سال نازل ہوئیں وہ بھی دو دفعہ دہرائی گئیں.کیونکہ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.آپ کی حیاتِ طیّبہ کے آخری سال میں جبریل علیہ السلام نے دو دفعہ قرآن کریم آپ کے ساتھ دہرایا اور یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے کہ ملائکہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جبریل علیہ السلام کا رمضان میں آپ کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا دَور کرنا نزول نہیں کہلا سکتا کیونکہ فرشتہ اُترتا ہی اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اور اسلامی زبان میں اس کے لئے نزول کی اصطلاح ہی استعمال ہوتی ہے.پس اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ کے ایک یہ معنے بھی ہیں کہ اس مہینہ میں تمام قرآن کا نزول ہوا.یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان اسلامی نام ہے اس مہینے کا پہلا نام زمانہ جاہلیت میں ناتق ہوا کرتا تھا.(فتح البیان)
Page 198
هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى.چونکہ ھُدًی اور بَیِّنَاتٍ دونوں قرآن کریم کا حال ہیں.اس لئے اس کے معنے یہ ہوئے کہ یہ قرآن ایسا ہے کہ اوّل تو وہ ھُدًی ہے یعنی لوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہے دوم اس میں ہدایت کے دلائل ہیں یعنی وہ یونہی لوگوں کو نہیں کہتا کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو بلکہ وہ دلائل بھی دیتا ہے.اور لِلنَّاسِ کا لفظ رکھ کر بتایا کہ یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہے صرف بعض لوگوں کے لئے نہیں.وَالْفُرْقَانَ اور پھر اس میں ایسے دلائل ہیں جو حق اور باطل میں امتیاز کردیتے ہیں.فَمَنْ شَھِدَ مِنْکُمُ الشَّھْرَ فَلْیَصُمْہُ میں بتایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کرے اور وہ ان دنوں میں سفر میں بھی نہ ہو اور اس کی صحت بھی اچھی ہو اُسے چاہیے کہ وہ پورے مہینہ کے مسلسل روزے رکھے اور اپنے لئے خیر اور برکت کے زیادہ سے زیادہ سامان جمع کرے اور ان مبارک ایام کو سستی اور غفلت میں ضائع نہ کرے.پھر فرماتا ہے یُرِیْدُ اللّٰہَ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَایُرِیْدُ بِکُمُ الْعُسْرَ.اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا.یعنی ہم نے رمضان میں روزے اس لئے مقرر کئے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تم ایمان لائو اور پھر اپنی زندگی تنگیوں میں بسر کرو.حالانکہ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان دنوں مومنوں کو اپنے نفس پر زیادہ تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے.درحقیقت اس آیت میں یہ عظیم الشان نکتہ بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے بھوکا رہنا یا دین کے لئے قربانیاں کرنا انسان کے لئے کسی نقصان کا موجب نہیں بلکہ سراسر فائدہ کا باعث ہوتا ہے.جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ رمضان میں انسان بھوکا رہتا ہے وہ قرآن کریم کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھوکے تھے ہم نے رمضان مقرر کیاتاکہ تم روٹی کھائو.پس معلوم ہوا کہ روٹی وہی ہے جو خدا کھلاتا ہے اور اصل زندگی اسی سے وابستہ ہے کہ انسان خدا کے لئے قربانی کر ےاور پھر جو کچھ ملے اسے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا کھائے.اس کے سوا جو روٹی ہے وہ دراصل کھانے والے کے لئے روحانی ہلاکت کا موجب ہوتی ہے.پس مومن کا فرض ہے کہ جو لقمہ بھی اس کے مونہہ میں جائے اس کے متعلق پہلے دیکھ لے کہ وہ کس کے لئے ہے ؟ اگر تو وہ خدا کے لئے ہے تو وہی روٹی ہے اور اگر نفس کے لئے ہے تو وہ روٹی نہیں بلکہ پتّھرہیں.اسی طرح جو کپڑا خدا کے لئے پہنا جائے وہی لباس ہے اور جو نفس کے لئے پہنتا ہے وہ ننگا ہے.دیکھو! کیسے لطیف پیرا یہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب تک تم خدا کے لئے تکالیف اور مصائب برداشت نہ کرو تم کبھی سہولت حاصل نہیں کر سکتے.اس سے ان لوگوں کے خیال کا بھی ابطال ہو جاتا ہے جو بقول حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام رمضان کو موٹے ہونے کا
Page 199
ذریعہ بنا لیتے ہیں.آپ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگوں کے لئے رمضان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے گھوڑے کے لئے خوید.وہ ان دنوں خوب گھی مٹھائیاں اور مرغن اغذیہ کھاتے ہیں اور اس طرح موٹے ہو کر نکلتے ہیں جس طرح خوید کے بعد گھوڑا.یہ چیز بھی رمضان کی برکت کو کم کرنے والی ہے.اسی طرح افطاری میں تنّوع اور سحری میں تکلّفات بھی نہیں ہونے چاہئیں اور یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سارا دن بھوکے رہے ہیں اب پُرخوری کر لیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ میں صحابہ کرام ؓ افطاری کے لئے کوئی تکلّفات نہ کرتے تھے.کوئی کھجور سے کوئی نمک سے بعض پانی سے اور بعض روٹی سے افطار کر لیتے تھے.ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اس طریق کو پھر جاری کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے نمونہ کو زندہ کریں.پھر فرماتا ہے وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّۃَ.اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو.مفسّرین نے اس کے یہ معنے کئے ہیں اور میں خود بھی کبھی کبھی یہ معنے کیا کرتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھر کے روزے مقرر کرنے کی وجہ بتائی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لئے مقرر کیا ہے تا دن پورے ہوجائیں.اگر یونہی حکم دے دیتا کہ روزے رکھو تو کوئی دس رکھ لیتا کوئی بیس رکھ لیتا اور کوئی رکھتا ہی چلا جاتا.پس اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کر دیا تاکہ روحانی تکمیل کے لئے جس مدت کی ضرورت ہے اس کو تم پورا کر لو.یہ معنے بھی اپنی جگہ درست ہیں مگر اس کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ اصل زندگی انسان کی وہی ہے جو نیکی میں گذرے.عمر کا وہ حصہ جو دنیا کے لئے گذر جاتا ہے ضائع چلا جاتا ہے.اس لحاظ سے اس کے یہ معنے ہیں کہ ہم نے روزے اس لئے رکھے ہیں تاکہ تم اپنی حقیقی عمر پوری کر لو.جو لوگ دنیا حاصل کرنے میں ہی مصروف رہتے ہیں وہ قرآنی اصطلاح کے مطابق زندہ نہیں بلکہ مُردہ ہوتے ہیں.اور مَنْ کَانَ فِیْ ھٰذِہٖ اَعْـمٰی فَھُوَ فِی الْاٰخِرَۃِ اَعْـمٰی (بنی اسرائیل:۷۳) کے مطابق جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ اگلے جہاں میں بھی اندھا ہی ہو گا.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.کہ ہم نے روزے اس لئے مقرر کئے ہیں تا تم دنیا میں اپنی مقررہ عمر گذار لو.چونکہ بنی نوع انسان کے لئے کھانا پینا لازمی ہے اس لئے سارا سال تو روزے نہیں رکھے جاسکتے تھے.اللہ تعالیٰ نے اس اصل کے مطابق کہ ایک نیکی کا ثواب کم سے کم دس ُگنا ملتا ہے ایک ماہ کے روزے مقرر کر دیئے اور اس طرح رمضان سارے سال کے روزوں کا قائم مقام ہو گیا.گویا جس نے اس مہینہ میں روزے رکھ لئے اس نے سارے سال کے روزے رکھ لئے اور اس طرح اس کی زندگی واقعی زندگی ہو گئی.پھر فرماتا ہے وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ.یہ روزے اس لئے مقرر کئے گئے ہیں کہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے.یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی
Page 200
فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایاتھا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے.اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شَھْر کے مقابلہ میں وَلِتُکْمِلُواالْعِدَّۃَ کے الفاظ رکھ دیئے اور بتایا کہ اگر ہم ایک مہینہ مقرر نہ کرتے تو کوئی کم روزے رکھتا اور کوئی زیادہ اور اس طرح وہ روحانی ترقی جو مہینہ بھر کے روزوں کے نتیجہ میں حاصل ہو سکتی ہے اسے وہ حاصل نہ کر سکتے.اس کے بعد اُنْزِلَ فِیْہِ الْقُرْاٰنُ کے مقابلہ میں وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ کے الفاظ رکھ کر بتایا کہ ہم نے کوئی اور مہینہ اس لئے مقرر نہیں کیا کہ نزول ِ قرآن کو یاد کر کے اس ماہ میں تمہارے دل میں خاص جوش پیدا ہو سکتا ہے.جب رمضان کا مہینہ آئےگا تو لازماً تمہیں یہ خیال بھی آئےگا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم پر خدا تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل قرآن کریم جیسی مقدّس کتاب کی شکل میں نازل ہوا ہے اور تمہارا دل خود بخود اس مہینہ میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی طرف متوجہ ہو جائےگا.پھر وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ میں اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ دن اس لئے ہیں کہ تا اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو یہ نہیں کہ تم شکوہ کرو کہ ہمیںبھوکا رکھا بلکہ یہ سمجھو کہ بڑا احسان کیا کہ روزہ جیسی نعمت ہمیں عطا کی.یہاں مومن کا نقطہ نگاہ واضح کیا گیا ہے کہ اسے قربانی کا جو مو قعہ بھی ملے وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے اور جس قوم کا یہ نقطہ نگاہ ہو جائے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا.وہ ضرور کامیاب ہو کر رہتی ہے.ایسی قوم حقیقی معنوں میں زندہ قوم ہو جاتی ہے.جب ایک شخص کے دل میں یہ خیال ہو کہ مجھ پر جو دینی ذمہ واریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرے گا اور جو شخص خدا تعالیٰ کی بڑائی کرے خدا تعالیٰ اس کی بڑائی کرتا ہے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں جو کوئی تحفہ دے تم اسے اس سے بہتر تحفہ دو.اور جب ہمیں یہ حکم دیاگیا ہے تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسا نہ کرے.انسان اس کی خدمت میں تحفہ پیش کرے اور وہ اس سے بہتر تحفہ اسے نہ دے.پس جو شخص خدا تعالیٰ کی بڑائی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی بڑائی کرتا ہے.مگر شرط یہی ہے کہ تکبیر صرف منہ سے نہ ہو.جس تکبیر سے وہ خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گالیاں کھائو.ماریں کھائو.پتھر کھائو اور پھر بھی خدا تعالیٰ کی تکبیر کرو کہ اس نے ہمیں یہ مواقع عطا کئے ہیں.گویا حقیقی تکبیر یہی ہے کہ جتنا زیادہ ظلم ہو اتنا ہی زیادہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف جھکے اور کہے کہ مجھ پر اس کے کتنے احسان ہو رہے ہیں جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرے اور اس کی بڑائی بیان کرے ایسے شخص کی تکبیر کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بڑھاتا ہے اور اس کی بڑائی کے سامان پیدا کرتا ہے.ورنہ صرف مُنہ کی تکبیر یں اس کے کسی کام نہیں آسکتیں.
Page 201
اس کے بعد فرمایا وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ.یہ روزے ہم نے اس لئے مقرر کئے ہیں تاکہ تم اس کے شکر گذار بنو.یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے وَ مَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ کے مقابل میں رکھ کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ سہولت ہم نے اس لئے رکھی ہے کہ تم شکر گذار بنو کہ خدا تعالیٰ نے مدارجِ عالیہ کے حصول کے لئے ہمارے لئے کس قدر سہولتیں رکھ دی ہیں اور تمہاری جبینِ نیاز ہمیشہ اس کے حضور جھکی رہے.غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین احکام دیئے ہیں اور تین ہی حکمتیں بیان فرمائی ہیں تین احکام تو یہ دیئے کہ (۱) مہینہ کے روزے رکھو (۲) رمضان میں رکھو (۳) مریض اور مسافر کو ان دنوں میں رخصت ہے.اس کے مقابل میں تین ہی حکمتیں بیان فرمائیں (۱) کہا تھا کہ ایک مہینہ کے روزے رکھو اس کے لئے فرمایا کہ اگر ہم روزے مقرر نہ کرتے تو لوگ کم و بیش رکھتے اور اس طرح وہ تعداد پوری نہ ہوتی جو روحانی ترقی کے لئے ضروری ہے (۲) کہا تھا کہ رمضان میں روزے رکھو.اس پر کوئی کہہ سکتا تھا کہ رمضان کو کیوں مقرر کیا ہے جس مہینہ میں کوئی چاہتا روزے رکھ لیتا اس لئے فرمایا کہ اس مہینہ میں قرآن کریم کا نزول یاد آکر خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کا جوش پیدا ہو گا اور اس مبارک مہینہ میں خدا تعالیٰ کی عبادت اور ذکرِ الہٰی کی طرف تمہیں زیادہ توجہ پید ا ہوگی.(۳) کہا تھا کہ بعض کے لئے رخصت ہے.اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان آسانیوں کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کا شکرادا کرنے کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ہمارا کتنا خیال ہے اس نے ہمارے فائدہ کے لئے حکم دیا اور اس میں بھی ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر دی ہیں.یہ عِدَّۃٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ کے مقابلہ میں فرمایا کہ یہ تخفیف اور سہولت اس لئے ہے کہ تم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس کی محبت سے اپنے سینہ و دل کو منور کرو.اسی طرح لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ رمضان ہم نے اس لئے اُتارا ہے کہ تم شکر گذار بنو.یعنی ہر تکبیر کے بعد شکر کرو کہ خدا نے اپنی تکبیر کی توفیق دی اور پھر اس بات کا شکر کرو کہ خدا نے اپنے شکر کی توفیق دی.اور پھر شکر کی توفیق ملنے پر شکر کرو.اس طرح اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائےگا کہ انسان ہر وقت اس کے دروازہ پر گِرا رہے گا اور اس غلام کی طرح ہو جائے گا جو کسی صورت میں بھی اپنے آقا کو نہیں چھوڑتا.
Page 202
وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ١ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ اور (اے رسول!)جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو (تُو جواب دے کہ)میں (ان کے) پاس الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ١ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ (ہی) ہوں.جب دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں.سو چاہیے کہ وہ (یعنی دعا کرنے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ۰۰۱۸۷ والے بھی)میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تا وہ ہدایت پائیں.حلّ لُغات.اُجیْبُ اَجَابَ سے مضارع متکلّم کاصیغہ ہے اور اَ لْاِجَا بَۃُ کے معنے ہیں اَلْعَطَاءُ مِنَ اللّٰہِ وَالطَّاعَۃُ مِنَ الْعَبْدِ (مفردات) یعنی اجابت اگر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو بخشش کرنے یا دینے کے معنے ہوتے ہیں اور اگر بندے کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنے اطاعت کے ہیں.پس اُجِیْبُ کے معنے ہوئے میں سن کر بدلہ دیتا ہوں یا اسے قبول کرتاہوں.وَلْیُؤْمِنُوْا بی اٰمَنَ بِہٖ کے معنے ہیں (۱) اُسے مان لیا (۲) اس کی صفات کو تسلیم کر لیا.پس وَلْیُؤْ مِنُوْا بِیْکے یہ معنے ہوئے کہ (۱) وہ مجھے مانیں اور (۲) میری صفات کو تسلیم کریں.لَعَلَّکُمْ لَعَلَّ مِنْ اَخَوَاتِ اِنَّ.لَعَلَّ اِنَّ کے اَخَوات میں سے ہے.وَذَکَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِیْنَ اَنَّ لَعَلَّ مِنَ اللّٰہِ وَاجِبٌ (مفردات) اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کے معنے یقین کے ہوتے ہیں.لَعَلَّ حروف مشبّہ بالفعل میں سے ہے اس کے ساتھ یائِ متکلم بھی لگائی جاتی ہے جیسے لَعَلِّیْ اور کبھی لَعَلَّاور یاء ِمتکلم کے درمیان نون زائد کیا جاتا ہے جسے نونِ وقا یہ کہتے ہیں جیسے لَعَلَّنِیْ.نون کے بغیر استعمال زیادہ ہے یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے جیسے لَعَلَّ زَیْدًا قَائِمٌ.لیکن فرَّاء اور بعض دیگر نحویوں کے نزدیک اسم اور خبر دونوں کو نصب دیتا ہے جیسے لَعَلَّ زَیْدًا قَائِـمًا.لَعَلَّکے کئی معنے ہیں (۱) پسندیدہ شے کی توقع اور ناپسندیدہ شے سے خوف ان معنوں میں یہ ایسے امر کے لئے
Page 203
استعمال ہوتا ہے جس کا حصول ممکن ہو گو مشکل ہو.قرآن کریم میں جو فرعون کاقول نقل ہے لَعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ.اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ.(المؤمن :۳۷ ،۳۸) اس کے متعلق مفسّرین کہتے ہیں یہ اس کی جہالت پر دلالت کرتا ہے وہ اپنی نادانی سے یہی سمجھتا ہو گا کہ میں اونچے مکان پر سے خدا تک پہنچنے کا راستہ پا لوں گا مگر میرے نزدیک یہ درست نہیں.میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ یا تو وہ یہ کہتا ہے کہ علم ہیئت کے ذریعہ سے موسیٰ کے مستقبل کو معلوم کر کے اس کا مقابلہ کروں گا اور یہ ُعقدہ گو باطل ہے مگر کثرت سے رائج ہے.یا پھر اس کا قول بطور تمسخر ہے.چونکہ موسیٰ ؑ بار بار خدا کو آسمان پر بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا اور فرشتے مجھ سے باتیں کرتے ہیں.اس پر وہ تمسخر سے کہتا ہے کہ لائو ایک مکان بنائو شائد اس طرح ہم موسیٰ کے خدا کو پہنچ جائیں اور ہم بھی اس سے باتیں کر کے دیکھیں.مطلب یہ کہ ایک طرف خدا کو آسمان پر ماننا اور دوسری طرف اس سے باتیں کرنے کا دعویٰ یہ خلافِ عقل ہے الٰہی علوم سے ناواقف انسانوں کے لئے اس مسئلہ کو نہ سمجھ سکنا قابلِ تعجب نہیں (۲) اس کے معنے محض تعلیل کے بھی ہوتے ہیں جیسے فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى(طٰہٰ : ۴۵) یہی معنے ترجمہ میں استعمال کئے گئے ہیں (۳) کوفیوں کے نزدیک کبھی اس کے معنوںمیں استفہام کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کلیات ابی البقاء میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ یعنی لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ(الشعراء: ۱۳۰)کے سوا جہاں کہیں بھی لَعَلَّ استعمال ہوا ہے توقع کے معنوں میں نہیں بلکہ تعلیل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی ’’تاکہ‘‘ یا ’’تا‘‘ کے معنوں میں (۴) کلام ِ ُملوک کے طو ر پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی بادشاہ کے لئے کوئی اور یا بادشاہ اپنی نسبت خود امید اور توقع کے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن مراد اس سے یقینی بات یا حکم کے ہوتے ہیں.تفسیر.فرماتا ہے اے میرےرسول! جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے سوال کریں اور پوچھیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے؟ جیسے عاشق پوچھتا پھرتا ہے کہ میرا محبوب کہاں ہے؟ تو تُو انہیں کہہ دے کہ تم گھبرائو نہیں َ میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں.یہاں عِبَادِیْ سے مراد عاشقانِ الہٰی ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح عاشق ہر جگہ دوڑا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا معشوق کہاں ہے؟ اسی طرح جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو تُو انہیں کہہ دے کہ گھبرائو نہیں میں تمہارے قریب ہی ہوں.کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عشاق کے دل کو توڑنا نہیں چاہتا.پھر فرماتا ہے.میرے قریب ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اُجِیْبُ دَعْوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.جب کوئی شخص کامل تڑپ اور سوز وگداز کے ساتھ مجھ سے دُعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں.اور یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات
Page 204
کا کہ میں قریب ہوں.اگر میں بعید ہوتا تو میں اس کی سجدے کی آہستہ آواز کو بھی کیسے سن سکتا؟ اور اگر میں بعید ہوتا تو اس کی گوشۂ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اُٹھا کر یا قیام کی صورت میں آہستہ آواز والی دُعا کیسے سُن لیتا.میرا اس دُعا کو سُن لینا بتاتا ہے کہ میں اس کے قریب ہوں.دوسری جگہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ (ق:۱۷)یعنی پاس ہونا تو الگ رہا جو انسان کی رگ ِ جان ہے ہم اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اس کے معنے یہ ہوئے کہ وہ پاس ہی نہیں بلکہ انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے.اور یہ ظاہر ہے کہ پاس بیٹھنے والا صرف وہ آواز سنتا ہے جو منہ سے کہی جائے اور جو اندر بیٹھا ہو وہ وہ بات سنتا ہے جو دل سے کہی جائے.گویا خدا تعالیٰ نے لفظ قریب کی دوسری جگہ تشریح کر دی کہ قریب کا مفہوم یہ ہے کہ حبل الورید یعنی رگِ جان سے بھی میں زیادہ قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں خواہ وہ زبان سے کی گئی ہو یا دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی ہو کیونکہ میرا اس سے تعلق ایسا قریب ہے کہ میں اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہوں.بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے اضطراب سے دعائیں کی تھیں مگر وہ قبول نہیں ہوئیں پھر یہ آیت کس طرح درست ثابت ہوئی؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بے شک اَلدَّاعِ کے ایک معنے ہر پکارنے والے کے بھی ہیں مگر اس کے ایک معنے ایسے پکارنے والے کے بھی ہیں جس کا اوپر ذکر ہو رہاہے.اور مراد یہ ہے کہ وہ بندے جو مجھے ملنے کے اضطراب میں اور سب کچھ بھول جاتے ہیں اور مجھ سے صرف میرا قرب اور وصال چاہتے ہیں میں ان کی دُعا کو سنتا اور انہیں اپنے قرب میں جگہ دیتا ہوں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں وَاِذَ ا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فرمایا ہے.یعنی وہ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں اس میں روٹی کا کہیں ذکرنہیں.نوکری کا کہیں ذکر نہیں بلکہ صرف عَنِّیْ فرمایا ہے عَنِ الْخُبْزِ یا عَنِ الْوَظِیْفَۃِ نہیں فرمایا.پس جو شخص خدا تعالیٰ کا قرب مانگے اور وہ اسے نہ ملے اسے تو بے شک اعتراض ہو سکتا ہے لیکن دوسروں کے لئے اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں.پھر اس آیت کی عبارت ایسی ہے کہ اس سے اضطراب اور گھبراہٹ کی طرف خاص طور پر اشارہ پایا جاتا ہے بعض مضامین الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتے لیکن وہ عبارت میں پنہاں ہوتے ہیں اور یہی حالت یہاں ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میری طرف دوڑتے ہیں.ان کے اندر ایک اضطراب اور عشق پیدا ہوتا ہے اور وہ چِلّاتے ہیں کہ ہمارا خدا کہاں ہے ؟تو تُو ان سے کہہ دے کہ میں تمہاری طرح کے پکارنے والے کی پکار کو کبھی ردّ نہیں کرتا بلکہ اُسے ضرور سنتا اور قبول کرتا ہوں.ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے
Page 205
وَالَّذِیْنَ جَاھَدُوْا فِیْنَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت:۷۰).یعنی وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ہمیں اپنی ذات ہی کی قسم ہے کہ ہم ضرور ان کو اپنے رستوں کی طرف آنے کی توفیق بخش دیتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مذہب اور علم کے آدمی کو اپنا رستہ دکھانے کے لئے تیار رہتا ہے.بشرطیکہ انسان اس کے لئے کوشش کرے.اور اس کی دُعا کو وہ ضرور سن لیتا ہے.باقی دعائوں کی قبولیت میں وہ انسانی مصالح کو بھی مدِّنظر رکھتا ہے بعض دفعہ انسان جو چیز مانگتا ہے خدا تعالیٰ کے علم میں وہ اس کے لئے مہلک ہوتی ہے.پھر بعض دفعہ ملازمت ایک ہوتی ہے اور اسے مانگنے والے دو ہوتے ہیں اب ایک ملازمت دو کو تو نہیں مل سکتی وہ لازماً ایک ہی کو ملے گی.مگر وہ چیز جس کے بانٹنے کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں آسکتی وہ خدتعالیٰ کی ذات ہے باقی تمام اشیاء محدود ہیں.اگر ایک چیز کے دو مانگنے والے سامنے آجائیں تو وہ لازماً زیادہ حقدار کو دی جائےگی یا اگر وہ مضر ہو تو گواس کا کوئی اور حقدار نہ ہو مگر پھر بھی وہ اپنے مومن بندہ کو نہیں دے گا.کیونکہ وہ دوست سے دشمنی کیونکر کر سکتا ہے اور کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کے متعلق وہ جانتا ہے کہ آگ ہے وہ اپنے دوست کو دےدے؟ غرض سب دعائوں کی قبولیت میں روکیں ہوتی ہیں مگر ایک دُعا ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی روک نہیں اور جس کے لینے میں کوئی برائی نہیں.دنیا کی ہر چیز میں برائی ہوسکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ (الماعون:۵) بعض نماز پڑھنے والوں کے لئے بھی ہلاکت ہے مگر خدا تعالیٰ کو مانگنے میں کوئی وَیلنہیں.کبھی ایسا نہیں ہو ا کہ خدا تعالیٰ کسی سے اس لئے نہ ملے کہ وہ ہلاکت میں نہ پڑے یااس لئے نہ ملے کہ خدا تعالیٰ کے وجود میں کمی نہ آجائے.جس طرح ہوا ہر ایک کے ناک میں جاتی ہے مگر اُس میں کمی نہیں ہوتی اسی طرح خدا تعالیٰ ہر بندہ کو مل سکتا ہے اور پھر بھی اس میں کمی نہیں ہوتی.سورج کی شعاعوں سے سب مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے.مگر ان میں کوئی کمی نہیں آتی چاند کی شعاعوں میں کوئی کمی نہیں آتی.تم چاند کی روشنی میں گھنٹوں بیٹھ کر لطف اٹھائو مگر اس کا نور پھر بھی اُتنے کا اتنا ہی رہے گا.یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے.بلکہ خدا تعالیٰ تو ان سے بھی کامل ہے.ان چیزوں میں بھی ممکن ہے کوئی خفیف سی کمی ہو جاتی ہو.مگر خدا تعالیٰ میں اتنی بھی نہیں ہوتی اسی لئے وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم میری طرف آئو.پھر تم دیکھو گے کہ تم کس طرح تیزی سے قدم مارتے ہوئے اس راستہ پر چل پڑو گے جس سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور باوجود یکہ وہ غیر مرئی ہے تم اس کو پالو گے اور اس کا وصال حاصل کر لو گے.درحقیقت اگر غور کیا جائے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی روحانی ترقی اور بندوں اور خدا کے باہمی اتصال کے لئے تین تغیرات کا ذکر فرمایا ہے جن کے بغیر کوئی انسان خدا تعالیٰ تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا.
Page 206
سب سے پہلا تغیر جو کسی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں خدا تعالیٰ سے ملوں اور اس کا قرب حاصل کروں.مگر ظاہر ہے کہ صرف خواہش کا پیدا ہونا اسے خدا تعالیٰ کے دربار تک نہیں پہنچا سکتا بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے کوئی ایسا ہادی اور رہنما میسر آئے جو اسے اس مقصد میں کامیابی کا طریق بتائے.اور اس کی مشکلات کو دُور کرے.اسلام اس فطری تقاضا کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ بیشک ان لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش تو پیدا ہو گئی ہے کہ انہیں خدا ملنا چاہیے لیکن اب دوسرا تغیر ان میں یہ بھی پیدا ہو نا چاہیے کہ وہ تجھ سے پوچھیں یعنی ہدایت پانے اور خدا تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لئے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی طرف جانا چاہیے اور آپ سے اپنے محبوب حقیقی کا پتہ دریافت کرنا چاہیے جس طرح بیمار کی تندرستی کے لئے ایک تو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سمجھ لے کہ وہ بیمار ہے اور دوسرے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جائے جو اعلیٰ درجہ کا تجربہ کار ہو.اسی طرح خدا تعالیٰ کو پانے کے لئے بھی ضروری ہے کہ نہ صرف خدا تعالیٰ کو پانے کی سچی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو بلکہ وہ اس خواہش کے حصول کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اختیار کر لے جو انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں.پھر تیسری بات جو قرب الٰہی کے لئے ضروری ہے اور جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا سوال عَنِّیْ ہو.یعنی ان کی غرض محض خدا تعالیٰ کو پانا ہو.لوگ کئی اغراض کے ماتحت مذہب میں داخل ہوتے ہیں.بعض لوگ محض ایک جماعت میں منسلک ہونے کے لئے داخل ہوتے ہیں بعض اخلاقِ فاضلہ کے حصول کے لئے داخل ہوتے ہیں بعض معاشرت یا تمدّن کے خیال سے داخل ہوتے ہیں مگر فرمایا ان کا سچے مذہب میں داخل ہونا محض خدا تعالیٰ کے وصال اور اس کے قرب کے حصول کے لئے ہو.کوئی اور خواہش اس کے پیچھے کام نہ کر رہی ہو.ہاں اگر دوسرے فوائد ضمنی طور پر حاصل ہو جائیں تو اور بات ہے لیکن اصل غرض محض خدا تعالیٰ کا حصول ہونا چاہیے.پھر عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اِذَا کے بعد ف آتی ہے تو اس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ پہلے کام کے نتیجہ میں فلاں بات پیدا ہوئی.اس جگہ بھی اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ کے یہ معنے ہیں کہ جب یہ تین باتیں جمع ہو جائیں.یعنی سوال کرنے والے سوال کریں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی ضرورت ہے.پھر تجھ سے سوال کریں فلاسفروں اور سائینس دانوں سے سوال نہ کریں.عیسٰی یاموسیٰ سے سوال نہ کریں بلکہ تیرے پاس آئیں قرآن کے پاس آئیں یا تیرے خلفاء کے پا س آئیں اور پھر وہ میری ذات کے متعلق سوال کریں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں ان
Page 207
کے قریب ہو جاتا ہوں اور انہیں اپنا چہرہ دکھا دیتا ہوں.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہےاور وہ یہ ہے کہ جب سورۃ قٓ میں جو کہ مکی سورۃ ہے خدا تعالیٰ یہ فرما چکا تھا کہ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ (قٓ : ۱۷) ہم انسان سے اس کی رگ ِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو پھر سورۃ بقرہ میں جو مدنی سورۃ ہے یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی کہ جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے سوال کریں تو ُتو اُن کو یہ جواب دے دے کہ َمیں قریب ہوں؟ جب مکی آیت کے ذریعہ ا نہیں معلوم ہو چکا تھا کہ خدا تعالیٰ بہت ہی قریب ہے تو پھر یہ سوال ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا.اس لئے اس آیت کے نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی.اور اگر کوئی سوال کرتا بھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسے یہ فرما سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ تو بتا چکا ہے کہنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ.لیکن قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بلا ضرورت نہیں ہوا کرتا.پس معلوم ہوا کہ یہاں خدا تعالیٰ کا سوال بیان کرنا اور پھر اس کا جواب دینا کوئی اَور حکمت رکھتا ہے.اور یہاں جو قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے اُس سے وہ قرب اور بُعد مراد نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے.کیونکہ اس کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ.اگریہاں بھی یہی مراد ہوتی تو پھر یہ کیوں فرماتا کہ جب لوگ تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یہ جواب دیجیؤ.پس معلوم ہوا کہ اس کے جواب میں جو قریب کہا گیا ہے وہ بھی کوئی اَور معنے رکھتاہے.یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان دونوں آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ایک عجیب فرق رکھا ہے.او روہ یہ کہ قرب اور بُعد ہمیشہ نسبت کے ساتھ ہوتا ہے ایک چیز ہمارے قریب ہوتی ہے مگر وہی دوسرے سے بعیدہوتی ہے.پس قریب اور بعید ایک نسبتی چیز ہے.جب ہم ایک چیز کو قریب کہتے ہیں تو ایک نسبت سے کہتے ہیں حالانکہ دوسری نسبت سے وہی چیز بعید ترین ہو سکتی ہے.سورۂ ق میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِہٖ نَفْسُہٗ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مَنْ حَبْلِ الْوَرِیْدِ.کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں جو وسوسہ ہوتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور ہم اس کی رگِ جان سے بھی قریب تر ہیں.تو اس میں اِلَیْہِ کی نسبت سے اَقْرَبُ فرمایا ہے.لیکن آیت وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ میں قَرِیْبٌ کا لفظ کسی نسبت سے نہیں فرمایا.بلکہ بلانسبت فرمایا ہے اور اس کی کوئی حد بندی نہیں کی.اس عدمِ حد بندی میں ایک لطیف نکتہ ہے اور وہ یہ کہ انسان جو اپنی ضرورت خدا تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف اشیاء کے متعلق ہوتی ہے کبھی تو وہ انسانوں کے متعلق ہوتی ہے او رکبھی حیوانوں کے متعلق.کبھی جانداروں کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی بے جانوں کے متعلق.کبھی
Page 208
خدا تعالیٰ کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی ملائکہ کے متعلق.کبھی اس دنیا کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی اگلے جہان کے متعلق.کبھی اس زمین پر رہنے والی چیزوں کے متعلق ہوتی ہے اور کبھی آسمان کی چیزوں کے متعلق.غرض انسان کی مختلف احتیاجیں ہیں اور ایسی وسیع ہیں کہ جن کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی.لیکن انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اسے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو اس کے حاصل کرنے کے متعلق وہ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کرتا ہے جو قریب ہو پھر قریب کی بھی کئی قسمیں ہیں.ایک یہ بھی قریب ہے کہ کوئی ذریعہ جلدی سے میسّر آجائے.چنانچہ ہر انسان اپنا مدّعا حاصل کرنے کے لئے جو ذریعہ قریب دیکھتا ہے اس کو لے لیتا ہے اور بعید کو چھوڑ دیتا ہے.مگر اس کے علاوہ قریب ایک اور رنگ میں بھی ہوتا ہے یعنی وہ ذریعہ جو مدّعا اور منزل مقصود کے قریب تر پہنچا دے انسان اس ذریعہ کو اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے.غرض بہت سے قرب ہیں جن کا کسی چیزمیں پایا جانا ہر انسان دیکھتا ہے اور جب وہ سارے قرب کسی میں پالیتا ہے تو اس کو اپنے مدّعا کے حصول کے لئے ُچن لیتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ کہ انسان اپنے مختلف مقاصد کے لئے کوشش کرتا ہے اور ان کے لئے دیکھتا ہے کہ کونسا ذریعہ اختیار کروں جس سے جلد کامیاب ہو جائوں.جب انسان ذرائع کو سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچے کہ مَیں دُعا کر وں تو اس کو کہہ دو کہ اللہ قریب ہے.قَرِیْبٌ اِلَیْہِ نہیں فرمایا.اس لئے کہ خدا تعالیٰ نہ صرف اس انسان کے قریب ہے بلکہ ہر ایک چیز کے قریب ہے اور وہ مدعا حاصل کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ ہے.یوں قریب ہونا اَور بات ہے لیکن جس مقصد کو حاصل کرنا ہو اس کے قریب کر دینا اور بات ہے.غرض خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے بھی قریب ہوں اور وہ مقصد جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے بھی قریب ہوں گویا اس آیت میں قربِ مکان کا ذکر نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حصولِ مدّعا کے لئے جتنے قربوں کی ضرورت ہے وہ سب خدا تعالیٰ میں موجود ہیں مثلاً ایک شخص ولایت میں بیٹھا ہوا روپیہ کا محتاج ہے وہ وہاں سے ہمیں مدد کے لئے لکھتا ہے.اگر ہم اُسے روپیہ بھیجیں تو کئی دنوں کے بعد اُسے ملے گا لیکن اگر ہم اس کے لئے دُعا کریں تو ممکن ہے کہ ادھر ہمارے منہ سےاس کے لئے دعا نکلے اور ادھر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی انتظام کر دے.تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں اگر کوئی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کہو.اور خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے لئے نہ ہاتھ ہلانے کی ضرور ت ہے نہ پائوں سے چلنے کی.دل ہی دل میں انسان حاضر ہو سکتا ہےکیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں.پھر وہ انسان ہی کے قریب نہیں بلکہ جس مدّعا اور مقصد کو حاصل کرنا ہو اس کے بھی قریب ہے.ادھر انسان یہ کہتا ہے کہ الہٰی فلاں چیز مجھے مل جائے اور ادھر وہ چیز خواہ لاکھوں میل کے فاصلہ پر ہو خدا تعالیٰ اس پراسی
Page 209
وقت قبضہ کر لیتا ہے کہ یہ ہمارے فلاں بندہ کے لئے ہے.کیونکہ جس طرح خدا تعالیٰ اس بندہ کے قریب ہے اسی طرح اس چیز کے بھی قریب ہے.غرض کامیابی کے حصول کے لئے یہ ذریعہ سب سے بڑا اورسب سے زیادہ مفید ہے.پھر اِنِّیْ قَرِیْبٌ کہہ کر ایک اور لطیف مضمون کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے اور وہ یہ کہ اگر میں تمہیں نظر نہیں آتا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تم سے دور ہوں میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں اور اسی وجہ سے تمہیں نظر نہیں آتا.کیونکہ صرف وہی چیز تمہیں نظر نہیں آتی جو زیادہ دور ہو بلکہ وہ چیز بھی نظر نہیں آتی جو زیادہ قریب ہو.یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی آواز کو نہیں سن سکتا کانشنس اور ضمیر کی آواز آتی ہے مگر کان اسے نہیں سن سکتے.اس لئے کہ آواز بھی دور کی سنائی دیتی ہے جب ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو اس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ یہ آواز باہر سے ہو کر آئی ہے.کیونکہ کان کا پردہ قدرتی طور پر اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہوا کا زور کان کے پردہ پر پڑتا ہے تو اس سے ایک حرکت پیدا ہوتی ہے ارتعاش کی لہریں یعنی وائی بریشنز( (VIBRATIONS پیدا ہوتی ہیں اور یہی وائی بریشنز دماغ میں جاتی ہیں اور دماغ ان کو الفاظ میں بدل ڈالتا ہے یہی وائی بریشن ہیں جو ریڈیو کے والوز میں پڑتی ہیں اور ریڈیو ان کو الفاظ میں بدل ڈالتا ہے.انسانی بناوٹ میں ریڈیو کان ہے اور اعصاب دماغی والوز ہیں.ان کے ذریعہ جو حرکات دماغ میں منتقل ہوتی ہیں وہ وہاں سے آواز بن کر سُنائی دیتی ہیں.پس آواز کے معنے ہی باہر والی چیز کے ہوتے ہیں.جب آواز آتی ہے تو اس کے یہی معنے ہوتے ہیں کہ یہ باہر سے آئی ہے کیونکہ آواز آ ہی باہر سے سکتی ہے.اندرونی آواز جو سنائی دیتی ہے.مثلا پیٹ میں گُڑ گُڑ کی آواز آتی ہے تو دراصل اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وائی بریشن باہر اثر ڈالتی ہیں اور ہم وہ آواز سن لیتے ہیں.ورنہ حقیقت یہی ہے کہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے اسے تم نہیں سن سکتے.کیونکہ وہ تمہارے زیادہ قریب ہوتی ہے.غرض جس طرح تم بہت بعید کی چیز کو نہیں دیکھ سکتے اور بہت قریب کی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتے.اسی طرح تم بعید کی آواز کو بھی نہیں سن سکتے اور قریب کی آواز کو بھی نہیں سن سکتے جن لوگوں کو اس کا علم نہیں وہ اس پر تعجب کریں تو کریں ورنہ یہ سب کچھ حرکات پر مبنی ہوتا ہے.جو کچھ تم سنتے ہو وہ بھی حرکات ہیں جن کو کان آواز میں بدل ڈالتے ہیں اور جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ بھی حرکات ہیں جن کو آنکھیں شکل میں تبدیل کر ڈالتی ہیں جو چیز تمہارے سامنے گڑی ہوتی ہے وہ تصویر نہیں ہوتی بلکہ وہ فیچرز(FEATURES)یعنی نقش ہوتے ہیں جو آنکھوں کے ذریعہ دماغ میں جاتے ہیں اور وہ انہیں تصویر میں بدل ڈالتا ہے.یہی وجہ ہے کہ آجکل ریڈیو سیٹ کے ذریعہ تصویریں بھی باہر جانے لگ پڑی ہیں.ان حرکات کے متعلق قاعدہ ہے کہ تمام حرکات خواہ وہ کان کی ہوں یا آنکھ کی ایک حد بندی
Page 210
کے اندر ہوتی ہیں یعنی ایک درجہ ان کا اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک ادنیٰ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان جو چیز ہوتی ہے اسے آنکھ دیکھ سکتی ہے اور جو چیز اس حد بندی سے دور ہو اسے آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جو اس حدبندی کے نیچے ہو اس کو بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی.اسی طرح جو آواز اس حد بندی کے اندر ہوگی اسے کان سن لے گا اور جو آواز اس حد بندی سے دور ہو گی اسے کان نہیں سن سکے گا.اور جو آواز اس حد بندی سے نیچے ہو اسے بھی کان نہیں سن سکتا.جَوّ میں بہت سی آوازیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جیسے بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز یا اجرام فلکی کے آپس میں ٹکرانے کی آواز لیکن وہ اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ہم ان کی شدت کی وجہ سے انہیں نہیں سن سکتے.جس طرح کان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ایسی آواز سن سکے جو اس کی طاقت سے باہر ہو.یا وہ ایسی آواز سن سکے جو اس کی طاقت سے کم ہو اسی طرح جو نظارہ آنکھ کی طاقت سے زیادہ ہو وہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی اور جو نظارہ اس کی طاقت سے کم ہو وہ بھی نہیں دیکھ سکتی.پس اِنِّیْ قَرِیْبٌ کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مجھ کو نہ دیکھنے کی یہ وجہ نہیں کہ میں تم سے دور ہوں میں تم سے دور نہیں بلکہ تمہارے اتنا قریب ہوں کہ تم مجھے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ تم میری آواز سن سکتے ہو.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں تو پھر وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ انسان پوچھتا تو اس کے متعلق ہے جو اُسے نظر آتا ہو.اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی سوال مبہم بھی ہوتا ہے.جیسے رات کو کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو اور اسے خطرہ محسوس ہو تو وہ آواز دیتا ہے کہ کوئی ہے؟ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اسے کوئی انسان نظر آرہا ہوتا ہے بلکہ وہ اس خیال سے آواز دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں ہوتو آئے اور اس کی مدد کرے اور جنگل میں تنہائی اور اندھیرے کی وجہ سے جو گھبراہٹ اس پر طاری ہے وہ دور ہو جائے.اسی طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں انسان تنہائی محسوس کرے اور سمجھے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور خدا تعالیٰ جو غیر مرئی ہے اس کے متعلق وہ کہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو آئے اور میری مدد کرے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے اُس بندے کو بتا دو کہ میں موجود ہوں اور پھر زیادہ دور بھی نہیں بلکہ میں تمہارے قریب ہی ہوں.دُنیا میں پاس رہنے والا شخص بھی بعض اوقات مدد نہیں کرتا.بعض دفعہ تو وہ مدد کا ارادہ ہی نہیں کرتا اور کہتا ہے مرتا ہے تو مر ے مجھے اس کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بعض اوقات وہ اپنے اندر زیادتی کرنے والے کے خلاف مدد کرنے کی طاقت نہیں پاتا.جیسے کوئی شیر گائوں میں آجائے او رکسی پر حملہ آور ہو تو دوسرے لوگ بجائے اس کی مدد کرنے کے بھاگ جاتے ہیں لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اگر کوئی بندہ گھبرا کر آواز
Page 211
دے اور کہے کہ کوئی ہے؟ تو وہاں خدا موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندے نے اگرچہ مبہم طور پر آواز دی ہے کہ شاید کوئی موجود ہو تو وہ بول پڑے لیکن میں اس کی مبہم پکار کو بھی اپنی طرف منسوب کر لیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے ہی بُلا رہا ہے.میں بھول جاتا ہوں کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے خیالی طور پر کہہ رہا ہے.میں اس وقت اگر مگر کو چھوڑ دیتا ہوں اور فوراً اس کی مدد کے لئے دوڑ پڑتا ہوں.اس لئے اگر کوئی میرے متعلق سوال کرے تو اُسے بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں، دور نہیں.بے شک دنیا میں بعض دفعہ کوئی دوسرا شخص قریب بھی ہوتا ہے تو پھر بھی وہ مدد کرنے کا ارادہ نہیں کرتا.یا اس کی مدد کی طاقت نہیں رکھتا لیکن میں تو یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہوں کہ اس کی مدد کروں گا.اور پھر میرے اندر اس کی مدد کرنے کی طاقت بھی ہے.اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ صرف مسلمانوں ہی کی دعائیں نہیں سنتا بلکہ خواہ کوئی ہندو ہو یا عیسائی، سکھ ہو یا آریہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے حضور سچے دل سے گڑ گڑائے اور اپنی حالت زار پیش کر کے اس کی مدد چاہے تو خدا تعالیٰ اس کی دُعا کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہے.بے شک وہ ایک سچے مسلمان کی دُعائیں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ قبول کرتا ہے.مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ اس نے اپنی رحمت کا دروازہ دنیا کی باقی قوموں اور افراد کے لئے بند کر رکھا ہے بلکہ ہر شخص جو اس کے دروازہ پر جاتا ہے اور اس کے حضور گر جاتا ہے خدا تعالیٰ اس پر رحم کرتا اور اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے وہ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.جب کوئی پکارنے والا اپنی مدد کے لئے مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کی پکار کا ضرور جواب دیتا ہوں اور اسے اپنی بارگاہ سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا.پھر فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ.جب میں تمہاری باتیں سنتا ہوں اور تمہاری دُعائیں قبول کرتا ہوں تو تمہیں بھی ایسا بن جانا چاہیے کہ تمہاری دُعائیں قبول ہوں.یہ مت خیال کرو کہ میں ہر ایک دُعا کو سنتا ہوں.میرے احکام کے خلاف جو دُعائیں ہوںگی یا میرے مقرر کردہ فرائض کے خلاف ہوںگی یا اخلاقی نظام کے خلاف ہوںگی میں انہیں کیسے سن سکتا ہوں.کیا میں انہیں قبول کر کے اپنے رسول کو ہلاک کردوں.یا کیا میں انہیں قبول کر کے اخلاقی نظام کو توڑ ڈالوں؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دُعائیںبھی سنی جائیں تو چاہیے کہ تمہاری دُعا میرے نظام کے خلاف نہ ہو.تمہاری دُعا دین کے خلاف نہ ہو.تمہاری دُعا اخلاقی نظام کے خلاف نہ ہو.کہتے ہیں ایک عرب حج کے لئے گیا تو وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کہ ایک دُعا کر رہا تھا اور وہ ایسی گندی تھی کہ اُسے سن کر پولیس نے اس کو قید کر لیا.وہ دُعا یہ کر رہا تھا کہ اے خدا! تو ایسا کر کہ میری محبوبہ کا خاوند اس سے نارا ض ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے.گویا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بھی اس کی بدکاری میں شریک ہو جائے.
Page 212
اسی طرح ایک دفعہ ایک چور نے بیان کیا کہ میں جب سیندھ لگانے لگتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھ لیتاہوں تاکہ چوری سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر لوں اور مجھے اس کام میں کامیابی حاصل ہو.اخبارات میں عموماً اشتہارات چھپتے رہتے ہیں کہ ایسے تعویذہیں جن کو پاس رکھنے سے تم جس عورت کو چاہو بلا سکتے ہو.اس تعویذ کے اثر سے وہ عورت خود بخود تمہارے پاس آجائےگی.اور پھر کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے اسے خدا تعالیٰ کا کلام آتا ہے.اس نے یہ تعویذ تیار کئے ہیں.یہ دین کے ساتھ تمسخر ہے.خدا تعالیٰ بدکاریوں میں کبھی شریک نہیں ہوتا.کہنے والے بیشک ایسا کہتے ہیں مگر یہ غلط ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہےفَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَ لْيُؤْمِنُوْا بِيْ.اگر میں نے کہا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سُنتا ہوں تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ہر ایک پکار کو سن لیتا ہوں جس پکار کو میں سُنتا ہوں اس کے لئے دو شرطیں ہیں.اول میں اس کی پکار کو سنتا ہوں جو میری بھی سنے (۲) میں اس کی پکار سنتا ہوں جسے مجھ پر یقین ہو مجھ پر بدظنّی نہ ہو.اگر دعا کرنے والے کو میری طاقتوں اور قوتوں پر یقین ہی نہیں تو میں اس کی پکار کو کیوں سنوں؟ پس قبولیت دعا کے لئے دو شرطیں ہیں جس دعا میں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی وہی قبول ہو گی.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں اَلدَّاعِ فرمایا ہے جس کے معنے ہیں ایک خاص دعا کرنے والا.اور اس کے آگے وہ شرائط بتا دیں.جو اَلدَّاعِ میں پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ میری سُنے اور مجھ پر یقین رکھے.یعنی وہ دُعا میرے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہو.جائز ہو ناجائز نہ ہو.اخلاق کے مطابق ہو.سنت کے مطابق ہو.اگر کوئی شخص ایسی دعائیں کرے گا تو میں بھی اس کی دعائوں کو سنوں گا.لیکن اگر کوئی کہے کہ اے اللہ! میرا فلاں عزیز مر گیا ہے تو اُسے زندہ کر دے تو یہ دعا قرآن کے خلاف ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے.جب اس نے قرآن کی ہی نہیں مانی.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں مانی تو خدا اس کی بات کیوں مان لے؟ پس فَلْیَسْتَجِیْبُوالِیْ وَلْیُوْ مِنُوْ ا بِیْ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم میری باتیں مانو اور مجھ پر یقین رکھو اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو میں تمہاری دُعا کیسے سُن سکتا ہوں؟ پس قبولیت دُعا کے لئے دو شرطیں ہیں.اولفَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ تم میری باتیں مانو(۲) وَلْیُوْ مِنُوْ ابِیْ اور مجھ پر یقین رکھو.جو لوگ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے وہ دین دار نہیں.وہ میرے احکام پر نہیں چلتے اس لئے میں بھی یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں ان کی ہر دُعا سُنوں گا.بیشک میں ان کی دُعائوں کو بھی سنتا ہوں مگر اس قانون کے ماتحت ان کی ہر دعا کو نہیں سنتا.لیکن جو شخص اس قانون پر چلتا ہے اور پھر دعائیں بھی کرتا ہے میں اس کی ہر دعا کو سنتا ہوں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ بازار میں چند بنیئے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا کوئی ایک پائو تلِ کھا سکتا ہے؟ وہ ایک پائو تل کھانا بہت بڑا کام سمجھتے تھے ان
Page 213
میں سے ایک نے کہا جو ایک پائو تل کھالے ا س کو میں پانچ روپے انعام دوںگا.پاس سے ایک زمیندار گذر رہا تھا اس نے جب سُنا کہ پائو تل کھانے پر شرط لگی ہوئی ہے تو اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اس نے خیال کیا کہ بھلا ایک پائو تل کھانا کون سی بڑی بات ہے جس پر انعام دیا جائے.ضرور اس کے ساتھ کوئی اور شرط ہو گی.وہ آگے بڑھا اور پوچھا شاہ جی ! ’’تل سلیاں سمیت کھانے نے کہ بغیر سلیاں دے.‘‘ یعنی پھلیوں سمیت تلِ کھانے ہیں یا الگ کئے ہوئے بیج کھانے ہیں.اس زمیندار کے نزدیک تو پائو تلِ کھاناکوئی چیز نہ تھی لیکن وہ سب بنئے تھے جو آدھا پھلکا کھانے کے عادی تھے.جب اس نے یہ کہا کہ شاہ جی کیا تل پھلیوں سمیت کھانے ہیں تو اس بنئے نے کہا چوہدری صاحب! آپ جائیے ہم تو آدمیوں کی باتیں کرتے ہیں.اسی طرح اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں وہاں بھی وہ آدمیوں کا ہی ذکر کرتا ہے.جانوروں کا ذکر نہیں کرتا.وہ ہر پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنتا.وہ صرف اس شخص کی پکار کو سنتا ہے جسے یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ پر ہی سب ذمہ داری نہیں بلکہ مجھ پر بھی کچھ ذمہ داری ہے.مثلاً اگر کوئی کہے کہ اے خدا! فلاں کی لڑکی مجھے اُدھال کر لا دے یا فلاں کا مال مجھے دے دے یا میرے فلاں شخص کی جان نکال دے تو خدا تعالیٰ اپنے آپ کو ان دُعائوں کا مخاطب نہیں سمجھتا پس فرمایا فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ میں ہر اس دعا کو سنتا ہوں جس کا کرنے والا پورے طور پر میرے احکام پر عمل کرے اور پھر اُسے مجھ پر پورا یقین بھی ہو اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط دُعائیں مانگتے ہی نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ ایسی دُعائیں مانگتے تھے کہ اے خدا! فلاں کا مال ظالمانہ طور پر ہمیں دےدے؟ پس خدا تعالیٰ بھی یہاں انسانوں کا ذکر کرتا ہے حیوانوں کا نہیں اور فرماتا ہے کہ میں دُعائیں سنتا ہوں لیکن اس کے لئے دو شرطیں ہیں.اوّل دُعا کرنے والا پورے طور پر میرے احکام پر عمل کرے.دوم.اسے مجھ پر یقین بھی ہو.جب اسے مجھ پر یقین ہو گا تو اس کا اعتماد بھی دعا کی قبولیت کے لئے اکسا ئے گا.حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ کس کے لئے دُعائیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میںسب سے زیادہ اس شخص کے لئے دعا کرتا ہوں جو مجھے آکر کہے کہ میرے لئے کوئی دعا کرنے والا نہیں آپ میرے لئے دعا کریں.جب وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے حالانکہ وہ میرا واقف بھی نہیں ہوتا تو میں اس پر اعتماد کیوں نہ کروں.پس فرمایا وَلْیُوْ مِنُوْابِیْ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے اور میرے منشا کے مطابق دُعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں.لیکن جسے یقین نہ ہو اور وہ میرے منشاء کے مطابق دعا نہ کرتا ہو تو اس کی دعا قبول نہیں ہوسکتی.اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ لَا یَزَالُ یُسْتَجَابُ
Page 214
لِلْعَبْدِ مَالَمْ یَدْعُ بِاِثْمٍ اَوْ قَطِیْعَۃِ رَحِمٍ مَالَمْ یَسْتَعْجِلْ.قِیْلَ! یَارَسُوْلَ اللّٰہِ مَا الْاِ سْتِعْجَالُ؟ قَالَ یَقُوْلُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَ رَ یَسْتَجِیْبُ لِیْ فَیَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَالِکَ وَیَدْعُ الدُّعَاءَ (مسلم کتاب الذکر و الدعاء باب بیان انہ یستجاب للداعی ما لم یعجل...)یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعائوں کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ قطع رحم اور گناہ کے متعلق نہ ہوں.مگر اس صورت میں نہیں کہ وہ جلدی کرے.صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ! جلدی سے کیا مرا دہے.آپ نے فرمایا وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے بڑی دُعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دُعا قبول نہیں ہوئی.پھر وہ دُعا سے تھک جاتا ہے اور دُعا چھوڑ بیٹھتا ہے.غرض دُعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور یقین رکھے اور مایوسی اس کے قریب بھی نہ پھٹکے.پھر فرماتا ہےلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.اس کے نتیجہ میں یقیناً وہ کامیاب ہوںگے.رشد کے معنے ہوتے ہیں رستہ دکھائی دینا.پس لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَکے معنے یہ ہیں کہ انہیں وہ رستہ مل جائےگا جو انہیں کامیابی تک پہنچا دےگا.(اقرب) لَعَلَّ کے معنے عام طور پر شاید کے ہوتے ہیں لیکن اس جگہ اس کے معنے شاید کے نہیں.یہاں یہ لفظ کلام الملوک کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے.چنانچہ بالعموم حکام کہہ دیتےہیں کہ اگر تم درخواست کرو تو حکومت غور کرے گی.لفظ شک کے ہوتے ہیں.لیکن دراصل وعدہ ہوتا ہے کہ ہم ضرور ایسا کر دیں گے.لغت والے بھی لکھتے ہیں کہ جب لَعَلَّ کا لفظ خدا تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس وقت اس کے معنے یقین کے ہوتے ہیں.(مفردات راغب) پس لَعَلَّھُمْ یَرْشُدُوْنَ کے یہ معنے ہیں کہ ابھی تک تو مجھے ان تک آنا پڑتا ہے مگر جب وہ یہ مقام حاصل کر لیں گے تو پھر ان کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جائےگی کہ وہ خود مجھ تک آسکیں گے.چنانچہ پہلے اِنِّیْ قَرِیْبٌ کہہ کر بتایا تھا کہ میں ان کے پاس آتا ہوں مگر یَرْشُدُوْنَ کہہ کر بتایا کہ بندہ میں ترقی کرتے کرتے ایک قسم کی الوہیت کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے پہلے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے نابینا آدمی کے پاس اس کا دوست بیٹھا رہے.مگر پھر یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جیسےبینا کے سامنے اس کا محبوب بیٹھا ہو.یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبادت کرتے وقت ہر انسان کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے.یا کم سے کم وہ یہ سمجھے کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے(بخاری کتاب الایمان باب سؤال جبریل النبی عن الایمان...).اب خدا تعالیٰ کے دیکھنے کے یہی معنے ہیں کہ وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے ورنہ دیکھ تو وہ عرش سے بھی رہا ہے درحقیقت اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کے اس قدر قریب آجاتا ہے کہ انسان یہ یقین کرنے لگ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے بلکہ اس سے ترقی کر کے وہ اس مقام کو بھی حاصل کر
Page 215
لیتا ہے جس میں وہ خود بھی خدا تعالیٰ کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور اعلیٰ درجہ کے کمالات روحانیہ تک پہنچ جاتا ہے.چونکہ اس آیت سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی روزوں کا ذکر ہے اس لئے اس آیت کے ذریعہ مومنوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی اپنے بندوں کی دُعائیں سُنتا اور ان کی حاجات کو پورافرماتا ہے لیکن رمضان المبار ک کےایام قبولیت دُعا کے لئے مخصوص ہیں.اس لئے تم ان دنوں سے فائدہ اُٹھائو اور خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو.ورنہ اگر رمضان کے مہینہ میں بھی تم خالی ہاتھ رہے تو تمہاری بد قسمتی میں کوئی شبہ نہیں ہو گا.دنیا میں ہر کام اپنے وقت کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اگر اس وقت وہ کام کیا جائے تو جیسے اعلیٰ درجہ کے نتائج اس وقت مرتّب ہوتے ہیں وہ دوسرے وقت میں نہیں ہوتے.تمام غلّے اور ترکاریاں بونے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے اگر اس وقت کو مدنظر نہ رکھا جائے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا.مگر وہ وقت جادو یا ٹونے کی طرح نہیں ہوتا کہ اس کے آنے سے کوئی خاص اثر پیدا ہو جاتا ہے اس لئے وہ کام ہو جاتا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جس وقت کسی کامیابی کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں تو وہی اس کے کرنے کا وقت ہوتا ہے اگر گیہوں کا دانہ ایک خاص وقت میں بونے سے اُگتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت اس میں کوئی خاص بات پیدا ہو جاتی ہے بلکہ اس کے اُگنے کے لئے جو سامان ضروری ہوتے ہیں وہ اس وقت مہیا ہو جاتے ہیں اگر وہی سامان کسی دوسرے وقت مہیا ہو سکیں تو اس وقت بھی وہ ضرور اُگ آئےگا.تو تمام کاموں کے لئے ضروری سامان مہیا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے.اسی طرح دُعا کے لئے بھی وقت مقرر ہیں ان وقتوں میں کی ہوئی دُعا بھی بہت بڑے نتائج پیدا کرتی ہے.جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِتَّقُوْا دَعْوَۃَ الْمَظْلُوْمِ (مسند احمد بن حنبل مسند المکثرین من الصحابۃ مسند انس بن مالکؓ ).مظلوم کی بد دعا سے ڈر و کیونکہ جب وہ ہر طرف مصائب ہی مصائب دیکھتا اور خدا تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں پاتا تو اس کی تمام تر توجہ خدا تعالیٰ کی طرف پھر جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے آگے گِر پڑتا ہے اور اس وقت وہ جو بھی دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے کیونکہ دعا کے قبول ہونے کے سامانوں میں سے ایک اعلیٰ درجہ کا سامان یہ بھی ہے کہ انسان کی ساری توجہ ہر طرف سے ہٹ کر خدا تعالیٰ ہی کی طرف ہو جائے.چونکہ مظلوم کی یہی حالت ہوتی ہے اس لئے اس کے لئے بھی یہ ایک موقع پیدا ہو جاتا ہے.اسی طرح دُعا کے قبول ہونے کے اوقات بھی ہیں.لیکن وہ ظاہری سامانوں کی حد بندیوں کے نیچے نہیں ہوتے بلکہ وہ انسانی قلوب کی خاص حالتوں اور کیفیات سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں وہی انسان محسوس کر سکتا ہے جس پر وہ حالت وارد ہو.مگر دُعا کی قبولیت کا ایک او ر وقت بھی ہے جس کے معلوم کرنے کے لئے باریک قلبی کیفیات سے
Page 216
واقف ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ وقت رمضان کا مہینہ ہے.یہ آیت خدا تعالیٰ نے روزوں کے ساتھ بیان کی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا روزوں سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس کے روزوں کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح مظلوم کی ساری توجہ محدود ہو کر ایک ہی طرف یعنی خدا تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے اسی طرح ماہِ رمضان میں مسلمانوں کی توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے.اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی پھیلی ہوئی چیز محدود ہو جائے تو اس کا زور بہت بڑھ جاتا ہے جیسے دریا کا پاٹ جہاں تنگ ہوتا ہے وہاں پانی کا بڑا زور ہوتا ہے اسی طرح رمضان کے مہینہ میں وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جو دعا کی قبولیت کا باعث بن جاتے ہیں.اس مہینہ میں مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہوتی ہے جو راتوں کو اُٹھ اُٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے.پھر سحری کے لئے سب کو اُٹھنا پڑتا ہے اور اس طرح ہر ایک کو کچھ نہ کچھ عبادت کا موقعہ مل جاتا ہے.اس وقت لاکھوں انسانوں کی دُعائیں جب خدا تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو رد نہیں کرتا.بلکہ انہیں قبول فرماتا ہے.اس وقت مومنوں کی جماعت ایک کرب کی حالت میں ہوتی ہے پھر کس طرح ممکن ہے کہ ان کی دُعا قبول نہ ہو؟ درد اور کرب کی حالت کی دعا ضرور سنی جاتی ہے جیسے یوُنسؑ کی قوم کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے ان کو بخش دیا اور ان سے عذاب ٹل گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سب اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور جھک گئے تھے.(یونس:۱۹) پس رمضان کا مہینہ دُعائوں کی قبولیت کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتا ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں دُعا کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قَرِیْبٌ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں.اگر وہ قریب ہونے پر بھی نہ مل سکے تو اور کب مل سکے گا؟ جب بندہ اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے کہ اب وہ خدا تعالیٰ کا درچھوڑ کر اور کہیں نہیں جائےگا تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں اور اِنِّیْ قَرِیْبٌ کی آواز خود اس کے کانوں میں بھی آنے لگتی ہے جس کے معنے سوائے اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے ؟اور جب کوئی بندہ اس مقام تک پہنچ جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خدا کو پالیا.اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ١ؕ هُنَّ تمہیں روزہ رکھنے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت ہے.وہ تمہارے لئے ایک (قسم کا) لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ١ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ لباس ہیں اور تم ان کے لئے (ایک قسم کا) لباس ہو.اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں
Page 217
كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفَا عَنْكُمْ١ۚ کی حق تلفی کرتے تھے اس لئےاس نے تم پر فضل سے توجہ کی اور تمہاری (اس حالت کی)اصلاح کر دی.فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ١۪ وَ كُلُوْا وَ سو اب تم (بلا تأمل) ان کے پاس جاؤاور جو کچھ اللہ (تعالیٰ) نے تمہارے لئے مقدر کیا ہے اس کی جستجو کرو.اور کھاؤ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ اور پیؤ.یہاں تک کہ تمہیں صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے.الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ١۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ١ۚ وَ لَا اس کے بعد(صبح سے) رات تک روزوں کی تکمیل کرو.اور جب تُبَاشِرُوْهُنَّ۠ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ١ۙ فِي الْمَسٰجِدِ١ؕ تِلْكَ تم مساجد میں معتکف ہو تو ان کے (یعنی عورتوں کے) پاس نہ جاؤ.یہ اللہ کی (مقررکردہ) حد یں ہیں حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا١ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ اس لئے تم ان کے قریب (بھی )مت جاؤ.اللہ (تعالیٰ) اسی طرح لوگوں کے لئے اپنے نشانات بیان کرتا ہے لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ۰۰۱۸۸ تاکہ وہ (ہلاکتوںسے) بچیں.حلّ لُغات.رَفَثٌ اَلرَّفَثُ کَلَامٌ مُتَضَمِّنٌ لِمَا یُسْتَقْبَحُ ذِکْرُ ہٗ مِنْ ذِکْرِ الْجَمَاعِ وَدَ وَاعِیْہِ وَجُعِلَ کَنَا یَۃً عَنِ الْجَمَاعِ.یعنی رَفَثَ کا لفظ جماع اور اس کے محرکات کے لئے کنایۃً استعمال ہوتا ہے.(مفردات) لِبَاسٌ لَّکُمْ لِبَاسٌکے معنے اصل میں سِتْرٌ کے ہیںیعنی ڈھانپنے والی چیز.مگر قرآن کریم نے اس کے اور
Page 218
معنے بھی بتائے ہیں.چنانچہ سورہ اعراف میں لباس کے دو کام بتائے گئے ہیں فرماتا ہے يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا(الاعراف: ۲۷) یعنی اے بنی آدم! ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے ننگ کو ڈھانکتا اور تمہیں زینت بخشتا ہے.لباس کا تیسرا کام ایک اور جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جَعَلَ لَکُمْ سَرَابِیْلَ تَقِیْکُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِیْلَ تَقِیْکُمْ بَاْسَکُمْ(النحل :۸۲) اس نے تمہارے لئے گرمی سردی کے ضرر سے بچانے کے لئے سرابیل بنائے ہیں.پس لباس کا تیسرا کام گرمی سردی کے ضر ر سے بچانا ہے.تَخْتَانُوْنَ خَانَ یَخُوْنُ سے باب افتعال ہے.اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے.اور اِخْتَانَہٗ اِخْتِیَانًا کے معنے ہیں اُؤْ تُمِنَ فَلَمْ یَنْصَحْ وَخَانَ الْعَھْدَ نَقَضَہٗ.یعنی اِخْتَانَ کے معنے ہیں امانت کا حق ادا نہ کیا اور عہد کو توڑا.(اقرب) عَفَا عَنْکُمْ عَفَا عَنْہُ وَلَہٗ ذَنْبَہٗ وَعَنْ ذَنْبِہٖ صَفَحَ عَنْہُ وَتَرَکَ عُقُوْبَتَہٗ وَ ھُوَ یَسْتَحِقُّھَا وَ اَعْرَضَ عَنْ مُؤَا خَذَ تِہٖ.یعنی عَفَا کے معنے ہیں (۱) اس کا قصور معاف کر دیا اور اس سے مواخذہ نہ کیا.(۲) اور عَفَااللّٰہُ عَنْ فُلَانٍ کے معنے ہیں مَحَا ذُنُوْبَہٗ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ مٹا دیئے.(اقرب) (۳) وَقَدْ یُسْتَعْمَلُ عَفَا اللّٰہُ عَنْکُمْ فِیْمَـا لَمْ یَسْبَقْ بِہٖ ذَنْبٌ وَلَا یُتَصَوَّرُ.عَفَا کا لفظ بعض دفعہ ایسے آدمی کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس نے نہ کوئی گناہ کیا ہو اور نہ اس کے متعلق گناہ کا خیال ہو سکتا ہو.(اقرب) بَاشِرُوْ ھُنَّ باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے اور بَاشَرَ الْاَمْرَ کے معنے ہیں تَوَلَّاہُ بِنَفْسِہٖ اس نے خود کوئی کام کیا.وَبَاشَرَہُ النَّعِیْمُ اَفَاضَ عَلَیْہِ حَتّٰی کَاَنَّہٗ مَسَّ بَشْرَ تَہٗ اور بَاشَرَ ہُ النَّعِیْمُ کے معنے ہیں اُسے اس کثرت سے نعمتیں حاصل ہوئیں کہ اس کے چمڑے کو چھونے لگیں.(اقرب) اور اَلْمُبَاشَرَۃُ کے معنے ہیں اَلْاِفْضَاءُ بِالْبَشْرَ تَیْنِ ہم صحبت ہونا.(مفردات) کَتَبَ اللّٰہُ لَکُمْ کَتَبَ لَہٗ میں عام طور پر لام فائدہ کے لئے آتا ہے اور کتابت کے معنے مقدر کردینے اور فرض کر دینے کے ہیں.اس جگہ مقدر کر دینے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے.مِنْ کے معنے اس جگہ امتیاز کے ہیں.عَاکِفُونَ عَاکِفٌ عَکَفَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور عَاکِفُوْنَ جمع کا صیغہ ہے.اور عَکَفَ کے معنے ہیں اَلْاِقْبَالُ عَلَی الشَّیْءِ وَ مُلَا زَمَتَہٗ عَلٰی سَبِیْلِ التَّعْظِیْمِ لَہٗ.یعنی کسی چیزکی طرف پوری طرح متوجہ ہونا.اور اس کے ساتھ اس کی تعظیم کی خاطر تعلق قائم رکھنا یا اس میں رہنا(مفردات).پس عَاکِفُوْنَ فِی الْمَسٰجِدِ
Page 219
کے معنے میں مسجدوں کو لازم پکڑنے والے اور ان میں بیٹھے رہنے والے.تفسیر.فرماتا ہے روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں سے بے تکلّف ہونا جائز ہے کیونکہ وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو.قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لباس کے تین کام بتائے گئے ہیں.اوّل.ننگ ڈھانکنا.دوم.زینت کا موجب ہونا.سوم.سردی گرمی کے ضرر سے انسانی جسم کو بچانا.چنانچہ فرماتا ہے يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا (الاعراف: ۲۷) یعنی اے آدم کی اولاد ! ہم نے تمہارے لئے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگ کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لئے زینت کا موجب بھی ہے.اسی طرح سورہ نحل میں فرماتا ہے.وَجَعَلَ لَکُمْ سَرَابِیْلَ تَقِیْکُمْ الْحَرَّ وَ سَرَابِیْلَ تَقِیْکُمْ بَاْسَکُمْ (النحل :۸۲) یعنی اس نے تمہارے لئے کئی قسم کی قمیصیں بنائی ہیں جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتی ہیں.اوربعض قمیصیں یعنی زر ہیں ایسی بھی ہیں جو تمہیں آپس کی جنگ کی سختی سے بچاتی ہیں.پس هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مردوں اور عورتوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں؟فرماتا ہے مردوں اور عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لئے ہمیشہ لباس کا کام دیں یعنی (۱) ایک دوسرے کے عیب چھپائیں (۲) ایک دوسرے کے لئے زینت کا موجب بنیں (۳) پھر جس طرح لباس سردی گرمی کے ضر ر سے انسانی جسم کو محفوظ رکھتا ہے اسی طرح مرد و عورت سُکھ دُکھ کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے کام آئیں.اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی دلجمعی اور سکون کا باعث بنیں.غرض جس طرح لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے اور اسے سرد ی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے اسی طرح انہیں ایک دوسرے کا محافظ ہونا چاہیے.حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال دیکھ لو.انہوں نے شادی کے معاً بعد کس طرح اپنا سارا مال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا.تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دقت پیش نہ آئے اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ خدمتِ خلق کے کاموں میں حصہ لیتے جائیں.یہ اہلی زندگی کو خوشگوار رکھنے کا کتنا شاندار نمونہ ہے جو انہوں نے پیش کیا.عَلِمَ اللّٰہُ اَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَکُمْ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے حقوق کو تلف کیا کرتے تھے اور ان کا پورا حق ادا نہیں کرتے تھے.پس اس نے تم پر اپنے فضل سے توجہ کی اور تمہاری اس حالت کی اصلاح کر دی.یہ حق تلفی جس کی طرف اس آیت میں اشار ہ کیا گیا ہے درحقیقت اس والہانہ عشق کی وجہ سے تھی جو صحابہؓ کے
Page 220
دلوں میں عبادت اور ذکر الہٰی کے متعلق پایا جاتا تھا.انہوں نے جب رمضان کی برکات کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ خدا تعالیٰ ان دنوں میں آسمان سے اُتر آتا ہے اور بندوں پر اپنے انوار اور برکات کی بارش نازل کرتا ہے تو انہوں نے چاہا کہ وہ رمضان کی راتیں بھی ذکر الہٰی اور عبادت میں بسر کریں اور جنسی تعلقات سے بالا رہیں.اسی طرح کھانے پینے کے متعلق بھی بعض ناواجب قیود انہوں نے اپنے اوپر عاید کر رکھی تھیں.چنانچہ بخاری میں حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت کے نزول سے قبل صحابہؓ میں سے جب کوئی شخص افطاری سے قبل سو جاتا تو آنکھ کھلنے پر وہ نہ رات بھر کچھ کھاتا اور نہ اگلے دن کھاتا یہاں تک کہ پھر دوبارہ شام کا وقت آجاتا.ایک دفعہ ایک انصاری جو روزہ دار تھے انہوں نے افطاری کے قریب اپنی بیوی سے کچھ کھانے کے لئے مانگا.اس نے کہاکہ گھر میں تو کچھ نہیں مگر کہیں سے کچھ مانگ لاتی ہوں.اتنے میں انہیں نیند آگئی او روہ سو گئے.بیوی باہر سے کھانا لے کر آئی تو چونکہ وہ سو چکے تھے اس لئے پرانے دستور کے مطابق وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے.نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ساری رات بھوکے رہے اور اگلے دن بھی ان کا روزہ ہی رہا.بارہ بجے کے قریب وہ شدت ضعف کی وجہ سے بیہوش ہو گئے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ١ؕ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی کہ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (بخاری کتاب الصوم باب قول اللہ جل ذکرہ احل لکم لیلۃ الصیام ) درحقیقت یہ پابندیاں یہود کی بعض رسوم کا نتیجہ تھیں.یہود میں یہ رواج تھا کہ وہ ایٹونمنٹ ڈے یعنی یوم کفارہ کا جب روزہ رکھتے تو ایک صبح سے دوسری صبح تک نہ کچھ کھاتے نہ پیتے (جیوش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Fasting private fasts)اُن کو دیکھ کر مسلمانوں کو بھی خیال پیدا ہوا کہ شاید جب آدمی سو جائے توا س کے بعد وہ کچھ نہیں کھا سکتا.اسی طرح مر دو عورت کے اختلاط کے متعلق ان کا خیال تھا کہ سارا رمضان جائز نہیں.بعض خیال کرتے تھے کہ جس وقت کھانا منع ہو وہ بھی منع ہے ان خیالات کی وجہ سے اگر کوئی سو جاتا تو کھانا نہ کھاتا اور اپنی بیوی کے پاس بھی نہ جاتا.اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بے فائدہ تکلیف ہے اس کی کچھ ضرورت نہیں صرف وہی پا بندی انسان کےلئے خیرو برکت کا موجب ہوتی ہے جو الٰہی منشاء کے مطابق ہو ورنہ بلا ضرورت اپنے آپ کو مختلف قیدوں اور پابندیوں میں جکڑ تے چلے جانا درست نہیں ہوتا.فَتَابَ عَلَیْکُمْ وَعَفَا عَنْکُمْ فرمایا کہ اب ہم نے تم پر رحم کر دیا ہے.اور تمہارے لئے آسانی بہم پہنچادی ہے اس لئے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور پہلے سے بھی زیادہ شوق اور مستعدی کے ساتھ نیک کاموں میں حصہ لو.
Page 221
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مومن بندے خدا تعالیٰ کی رضا ء کےلئے اپنے آپ کو کسی مشقت میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ش میں آتی ہے اور وہ کسی نہ کسی شکل میں انسان کے لئے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے.گویا اُن کے اخلاص کا انہیں دم نقد فائدہ دے دیتا ہے.پھر فرماتا ہے فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ.کَتَبَ عَلَیْہِ اورکَتَبَ لَہٗ میں فرق ہے.کَتَبَ عَلَیْہِ کے معنے ہوتے ہیں.اُس پر فرض کیا گیا ہے.اور کَتَبَ لَہٗ کے معنے ہوتے ہیں اس کےلئے کوئی انعام مقرر کیا گیا ہے.یا کوئی حق مقرر کیا گیا ہے.(یا استعارۃً تقدیر مقررہ کے معنوں میں بھی آجاتا ہے )پس اس آیت کے یہ معنے ہوئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارا حق مقرر کیا ہےاس کو چاہو یعنی جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز کیا ہے یا جن سے نہیں روکا اُن کو بے شک کرو.وہ تمہارا حق ہیں.اُن کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں.یا یہ کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر کر رکھی ہے.اُس کی جستجو کرو یعنی جو طریق اولاد حاصل کرنےکا اُس نے مقرر کر رکھا ہے اس کے مطابق عمل کرو.اسی طرح وَ ابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْسے یہ بھی مراد ہے کہ اس مقدس مہینہ میں جو کچھ برکات خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر کر رکھی ہیں ان کے حصول کے لئے پوری کوشش کرو.پہلا طریق جو حقوق نفس کو تلف کرنے والا تھا اس کے نتیجہ میں ممکن تھا کہ تمہارے جسم کو کوئی نقصان پہنچ جاتا اور تم زیادہ محنت اور مشقّت نہ کر سکتے.مگر اب جبکہ ہم نے اس کی تلافی کر دی ہے اور تمہارے جسم کو بے جا کوفت سے بچالیا ہے تمہارا فرض ہے کہ تم کمر ہمت باندھ کر خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اُن درجاتِ عالیہ کی تلاش کرو جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر کر رکھا ہے.وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.فرماتا ہے تم اس وقت تک کھاؤ پیئو جب تک کہ تمہیں صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے.جب یہ آیت نازل ہوئی تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ ؓ نے غلطی سے سیاہ اور سفید دھاگے اپنے پاس رکھنے شروع کر دئیے اور انہوں نے خیال کیا کہ ہمیں اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک کہ ہمیں سفید اور سیاہ دھاگے میں فرق نظر نہ آنے لگے.چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عدیؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ! میں نے سیاہ اور سفید دو دھاگے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ دئیے ہیں تاکہ جب سیاہ اور سفید دھاگے میں فرق نظر آنے لگے تو مجھے معلوم ہو جائے
Page 222
کہ اب کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اُن کی یہ بات سن کر فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے کہ اُس کے نیچے خیط ابیض اور خیط اسود دونوں آگئے ہیں.پھر آپ نے فرمایا.اس سے مراد تو صرف رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی ہے.ظاہر ی دھاگے مراد نہیں ہیں (مسلم کتاب الصّیام باب بیان أن الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر....) اسی طرح بعض اور صحابہ ؓ بھی سفید اور سیاہ دھاگے اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور وہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے تھے جب تک کہ ان دونوں میں انہیں فرق نظر نہ آجاتا.آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ مِنَ الْفَجْرِ کے الفاظ نازل فرمائے تب انہیں معلوم ہوا کہ خیط ابیض اور خیط اسود سے سفید اور سیاہ دھاگا مراد نہیں بلکہ اس سے صبح صادق اور صبح کا ذب کا فرق مراد ہے.پنجاب میں بھی بعض زمیندار رمضان کی راتوں میں سفید اور سیاہ دھاگا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں.اور چونکہ دھاگا اچھی روشنی میں نظر آتا ہے مدھم روشنی میں نظر نہیں آتا اس لئے وہ کافی روشنی ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں.بلکہ بعض لوگوں کی نظر چونکہ کمزور ہوتی ہے اس لئے ممکن ہے وہ دن چڑھنے کے بعد بھی اس آیت کی روسے کھانے پینے کا جواز ثابت کر لیں کیونکہ انہیں سورج کی روشنی میں ہی اس فرق کا پتہ لگ سکتا ہے.بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خیط ابیض اور خیط اسود کے الفاظ استعارۃً استعمال فرمائے ہیں.اور مراد یہ ہے کہ صرف اس وہم کی بنا پر کھانا پینا ترک نہیں کر دینا چاہیے کہ ممکن ہے صبح ہو گئی ہو بلکہ اس کےلئے ضروری ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب میں امتیاز ہو جائے اور پَوپھٹ جائے.ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ.اس جگہ لیل سے گہری تاریکی مراد نہیں بلکہ صرف سورج غروب ہونے کا وقت مراد ہے.چنانچہ احادیث میں آتاہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا یَزَالُ النَّاسُ بِخَیْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ (مسلم کتاب الصیام باب فضل السحور و تاکید استحبابہ...) کہ جب تک لوگ سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرتے رہیں گے اُس وقت تک وہ خیر پر قائم رہیں گے.یعنی احکام اسلامی کی حقیقی روح ان میں زندہ رہے گی.ورنہ جب لوگ رسوم یا وہم سے کام لینے لگتے ہیںتو فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں اور اُن کے اوہام انہیں دور ازکار باتوں میں الجھا دیتے ہیں اور اُن کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہو جاتی ہے.جو نماز کی نیت باندھتے ہوئے اپنے وہم میں اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ پہلے تو امام کو انگلی مار مار کر کہتا کہ پیچھے اس امام کے اور پھر رفتہ رفتہ اُس نے امام کو دھکے دینے شروع کر دئیے.اِسی طرح جن لوگوں کاوہم بڑھ جاتا ہے وہ پہلےتو سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتے ہیں.مگر چونکہ ابھی سُرخی باقی ہوتی ہے اس لئے ان کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ زیادہ انتظار کرتے ہیں.
Page 223
یہاں تک کہ جب گہری تاریکی چھا جائے تب افطاری کرتے ہیں.یہ طریق شریعت کے خلاف ہے.اللہ تعالیٰ نے اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ کا حکم دیا ہے اور لیل کا وقت سورج ڈوبنے سے لےکر سورج نکلنے تک ہے.یہ مراد نہیں کہ جب تک اچھی طرح تاریکی نہ چھا جائے اس وقت تک تم روزہ افطار ہی نہ کرو.وَ لَا تُبَاشِرُوْهُنَّ۠ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ.اس کے متعلق اختلاف ہوا ہے کہ آیا اعتکاف کی وجہ سے مباشرت ممنوع قرار دی گئی ہے یا مسجد کی حرمت کی وجہ سے (تفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت ھذا).میرے نزدیک اعتکاف کی وجہ سے مباشرت سے نہیں روکا گیا بلکہ مسجد کے احترام کی وجہ سے روکا گیا ہے.جس کی طرف ۠ وَ اَنْتُمْ عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِکے الفاظ اشارہ کر رہے ہیںکہ مباشرت کی نفی اعتکاف کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مساجد کی وجہ سے ہے.لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مباشرت لَمَس کو بھی کہتے ہیں اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی حالت میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے آپ کا سر بھی پانی سے دھودیتی تھیںاور بالوں کی کنگھی بھی کر دیا کرتی تھیں (بخاری ابواب الاعتکاف باب لا یدخل البیت الا لحاجۃ ).پس اس جگہ مباشرت کی نہی سے محض مخصوص تعلقات یا اُس کے مبادی مراد ہیں جسم کو چھونا مراد نہیں.تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا.فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں.تم اُن کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ غلطی سے تمہارا قدم اللہ تعالیٰ کے محارم میں نہ جا پڑے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓکو اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو! حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور بھی ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے.پس جو شخص ان مشتبہ امور سے بچا اُس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچانے کےلئے بڑی احتیاط سے کام لیا.لیکن جو شخص ان مشتبہ امور میں جا پڑا وہ اس چروا ہے کی مانند ہے جو رکھ کے آس پاس اپنا ریوڑ چرارہا ہے.اور قریب ہے کہ اُس کا ریوڑ رکھ کے اندر چلا جائے.پھر آپ نے فرمایا کہ اَلَا وَاِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حِمًی اَلَا اِنَّ حِمَی اللّٰہِ فِیْ اَرْضِہٖ مَحَارِمُہٗ.کان کھول کر سنو! کہ ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کی رکھ اُس کی حرام کردہ چیزیں ہیں (بخاری کتاب الایمان باب فضل من اِسْتَبْرَأَ لدینہٖ) پس محارم اللہ تعالیٰ کی رکھ ہوتے ہیں اور اگر کوئی انسان اُن کے قریب جائے تو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اُس کا قدم ڈگمگا جائے اور وہ ناجائز امور کا مرتکب ہو کر خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موردبن جائے.پس اصل تقویٰ یہی ہے کہ انسان حدود اللہ کے قریب جانے سے بھی بچے تاکہ شیطان اُس کے قدم کو ڈگمگانہ دے.
Page 224
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ.اس میںآیات سے مراد احکام الٰہیہ ہیں اور فرماتا ہے کہ ان احکام کی اصل غرض تمہارےاندر تقویٰ پیدا کرنا ہے.پس تمہیں چاہیے کہ تم ہمیشہ تقوی اللہ کو ملحوظ رکھو اور نہ صرف اللہ کی حدود کو نہ توڑو بلکہ شبہات سے بھی پرے رہنے کی کوشش کرومبادا تمہارا قدم پھسل جائے اور تم تقویٰ سے دور چلے جاؤ.وَ لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى اور تم اپنے (بھائیوںکے ) مال آپس میں (مل کر) جھوٹ (اور فریب) کے ذریعہ سے مت کھاؤ.اور نہ ان الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ (اموال)کو (اس غرض سے ) حکّام کی طرف کھینچ لے جاؤتا تم لوگوں کےمالوں کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہوئے وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَؒ۰۰۱۸۹ ناجائز طورپر ہضم کر جاؤ.حلّ لُغات.تَاْکُلُوْا اَکَلَ کے معنے کھانے کے ہوتے ہیں.لیکن جب غذا کے سوا اور چیزوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے ہلاک کرنے یا فنا کر دینے کے ہوتے ہیں.تُدْلُوْا اَدْلٰی سے جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور اَدْلٰی اِدْلَاءً کے معنے ہیں اَرْسَلَ الدَّلْوَ فِی الْبِئْرِ، اس نے کوئیں میں ڈول ڈالا اور اَدْلٰی فُلَا نٌ فِی فُلَانٍ کے معنے ہیں.قَالَ قَبِیْحًا اس نے کسی کے متعلق بُری بات کہی اور اَدْلٰی بِـحُجَّتِہٖ کے معنے ہیں اس نے اپنی دلیل پیش کی اور اَدْلٰی اِلَیْہِ بِمَالٍ کے معنے ہیں.اس نے اُسے مال دیا.(اقرب) تُدْلُوْا بِھَا اصل میں لَا تُدْلُوْ ابِھَا کے معنوں میں ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ (۱) ایک دوسرے کے مال حکّام کے پاس نہ لے جائو.یعنی جھوٹے مقدمات بنا کر اُن کے مال نہ لو (۲) حاکموں کو بطور رشوت مال نہ دو.تفسیر.اپنے مال کو تو انسان کھایا ہی کرتا ہے پس لَا تَاْکُلُوْا اَمْوَالَکُمْ سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ مت کھائو.انسان دوسرے کا مال کئی طرح کھاتا ہے.اوّل.جھوٹ بول کر.دوم.ناجائز ذرائع سے چھین کر.سوم.سود کے ذریعہ سے.چہارم رشوت لے کر یہ سب امور باطل میں داخل ہیں.
Page 225
وَ تُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ میں بتایا کہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا مال کھانا ناجائز ہے.اسی طرح تم حکام کو بھی روپیہ کا لالچ نہ دو تاکہ اس ذریعہ سے تم دوسرے کا مال کھا سکو.اس آیت میں افسران بالا کو رشوت دینے کی ممانعت کی گئی ہے اور اُسے حرام اور ناجائز قرار دیا گیاہے.دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ اپنے مالوں کو حکّام کے پاس نہ لے جائو تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ کے ذریعہ کھا جائو.یعنی ان کے متعلق جھوٹے مقدمات دائر نہ کرو اور یہ نہ سمجھو کہ اگر حاکم انصاف کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے تمہیں کسی کا حق دلادے گا تو وہ تمہارے لئے جائز ہو جائےگا کیونکہ دنیوی عدالتوں سے بالا ایک آسمانی عدالت بھی ہے اور جب اس نے اپنے قانون میں ایک چیز کو ناجائز قرار دے دیا ہے تو دنیا کی کوئی عدالت خواہ اُسے جائز بھی قرار دے دے وہ بہر حال ناجائز اور حرام ہی رہے گا.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا فَمَنْ قَضَیْتُ لَہٗ بِحَقِّ اَخِیْہِ شَیْئًا فَلَا یَاْ خُذُہٗ.فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَہٗ قِطْعَۃً مِّنَ النَّارِ.(بخاری کتاب الاحکام باب موعظۃ الامام للخصوم) یعنی اگر میں کسی شخص کے لئے اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا غلط فیصلہ کر دوں تو اُسے چاہیے کہ وہ اس کے لینے سے انکار کر دے کیونکہ میں اس کے لئے آگ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں.اسی طرح بخاری اور مسلم میں اُمّ المومنین حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت آتی ہے کہ اَنَّہٗ سَمِعَ خُصُوْمَۃً بِبَابِ حُجْرَتِہٖ فَخَرَجَ اِلَیْھِمْ فَقَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَ اِنَّہٗ یَاْ تِیْنِی الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَکُمْ اَنْ یَّکُوْنَ اَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَاَحْسِبُ اَنَّہٗ صَادِقٌ فَاَقْضِیَ لَہٗ بِذٰلِکَ فَمَنْ قَضَیْتُ لَہٗ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَاِنَّمَا ھِیَ قِطْعَۃٌ مِّنَ النَّارِ فَلْیَاْ خُذْ ھَااَوْلِیَتْرُکْھَا.(بخاری کتاب الاحکام باب من قضی لہ بحقّ اخیہ فلا یاخذہ...) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے مکان کے دروازہ پر کسی جھگڑے کی آواز سنی آپ شور سُن کر باہر تشریف لے آئے اور لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں.میرے پاس مقدمات والے آتے ہیں تو ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو.اور میں اس کی باتوں کی وجہ سے خیال کرلوں کہ وہی سچا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں.پس اگر میں کوئی ایسا فیصلہ کر دوں تو جس شخص کےلئے میں کسی مسلمان کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں اُسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے اُسے دیا ہے اور اسے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس آگ کے ٹکڑا پر قبضہ کر لے اور چاہے تو اُسے چھوڑ دے.
Page 226
يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ١ؕ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَ تجھ سے چاندوں کے بارہ میں سوال کرتے ہیں.تو کہہ دے کہ یہ لوگوں (کے عام کاموں) اور حج کے لئے وقت الْحَجِّ١ؕ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَ معلوم کرنے کا آلہ ہیں اور اعلیٰ نیکی یہ نہیں ہےکہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے داخل ہو بلکہ کامل نیک وہ شخص لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى١ۚ وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا١۪ وَ اتَّقُوا ہے جو تقویٰ اختیار کرے.اور (تم) گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو.اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۰۰۱۹۰ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.حل لغات.اَ لْاَ ھِلَّۃُ ھَلَالٌ کی جمع ہے.وَقِیْلَ یُسَمّٰی ھِلَا لًا لِلَیْلَتَیْنِ اَوْ اِلٰی ثَلَاثٍ اَوْ اِلٰی سَبْعٍ.اور ہلال دوراتوں کے چاند کو کہتے ہیں.اسی طرح تین اور سات راتوں کے چاند کو بھی ہلال کہا گیا ہے.(اقرب الموارد) مَوَاقِیْتُ مِیْقَاتٌ کی جمع ہے اور اَلْمِیْقَاتُ کے معنے ہیں.اَلْوَقْتُ وقت.وَقِیْلَ اَلْوَقْتُ الْمَضْرُوْبُ لِلشَّیْءِ.اور کہا گیا ہے کہ میقات سے مراد وہ خاص وقت بھی ہے جو کسی کام کے لئے مقرر کیا جائے.وَالْمَوْعِدُ الَّذِیْ جُعِلَ لَہٗ وَقْتٌ.اور میقات اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے لئے کوئی وقت مقرر کیا گیا ہو.وَقَدْ یُسْتَعَارُ لِلْمَوْضِعِ الَّذِیْ جُعِلَ وَقْتًا لِلشَّیْءِ.اور وہ خاص جگہ جہاں کوئی خاص کام وقت مقررہ پر کیا جائے اُسے بھی میقات کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.صحابہ کرامؓ نے جب دیکھاکہ کس طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ان کے قریب آجاتا اور ان کی دُعائوں کو قبول فرماتا ہے تو ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوا کہ وہ باقی مہینوں کے بارہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے سوال کریں تاکہ وہ ان کی برکات سے بھی مستفیض ہو سکیں.چنانچہ فرماتا ہےکہ لوگ تجھ سے چاندوں کے بارہ میں سوال کرتے ہیں تو انہیں کہہ دے کہهِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ یہ لوگوں کے لئے وقت کا اندازہ
Page 227
کرنے کا ایک ذریعہ ہیں.یعنی ہر قمری مہینہ اس لئے مقرر نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ شریعت کے کسی خاص حکم کا تعلق ہے بلکہ ان مہینوں کا چاند کے ساتھ اس لئے تعلق رکھا گیا ہے کہ ان کے ذریعہ گذشتہ یا آئندہ کام کا وقت پہچانا جاتا ہے اور پھر لِلنَّاسِ فرما کر بتایا کہ عوام کے فائدہ کے لئے یہی چاند کے مہینے کام دیتے ہیں.ورنہ وہ حساب جس کی سورج کی گردش پر بنیاد ہے اس سے صرف علمی طبقہ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے عام لوگ اس سے فائدہ اُٹھانے کی استعداد نہیں رکھتے.پھر فرمایا وَ الْحَجِّ.قمری مہینوں کا دوسرا فائدہ حج سے تعلق رکھتا ہے یعنی بوجہ اس کے کہ حج کا فریضہ قمری مہینہ میں ادا کیا جاتا ہے.یہ عبادت سارے سال میں چکر لگاتی رہتی ہے اور مختلف طبائع کے لوگ اور گرم سرد ممالک کے رہنے والے اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے حالات کے مطابق اس میں حصہ لے سکتے ہیں.اگر حج کسی شمسی مہینہ میں مقرر کر دیا جاتا تو لازماً وہ ہر سال ایک ہی مہینہ میں ہوتا اور کئی لوگوں کے لئے حج کا فریضہ ادا کرنا ناممکن ہو جاتا.مگر اب حج کی عبادت سارے سال میں چکر لگاتی رہتی ہے اور ہر شخص اپنے اپنے حالات کے مطابق بیت اللہ کا سفر کر کے حج کی برکات سے مستفیض ہو سکتا ہے.هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے نزدیک چاند ہی وقت کا اندازہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے.کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں سورج کو بھی وقت کا اندازہ کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے.چنانچہ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ (یونس: ۶) یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے سورج کو اپنی ذات میں ایک روشن وجود بنایا ہے اور چاند کو نور بنایا ہے جوسورج سے اکتسابِ نور کر رہا ہے.اسی طرح سورج اور چاند کی ہم نے منازل مقرر کر دی ہیں تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور حساب معلوم ہوا کرے.پھر سور ۃانعام میں فرماتا ہے فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا١ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (الانعام: ۹۷) یعنی خدا صبح کو ظاہر کرنے والا ہے اور اس نے رات کو سکون اور آرام کا موجب اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا اور یہ فیصلہ ایک غالب اور علم رکھنے والے خدا کا ہے.اسی طرح سورہ رحمٰن میں فرماتا ہے اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (الرحمٰن :۶) سورج اور چاند دونوں ایک حساب کے ماتحت کام کر رہے ہیں یعنی ان کی حرکات قانون سے آزاد نہیں بلکہ ایک معین اور مقرر ہ قانون کے مطابق ہیں اور اسی مقررہ قانون کا یہ نتیجہ ہے کہ وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ (الرحمٰن :۷) زمین کی روئیدگی اور سبزہ سب اپنے اُگنے ،نشوونما پانے اور پھل لانے میں سورج اور چاند کے پیچھے چلتے ہیں اور ان سے متاثر ہوتے ہیں.
Page 228
ان آیات قرآنیہ سے واضح ہے کہ تاریخ اور حساب کے ساتھ سورج اور چاند دونوں کا تعلق ہے.اور یہ علوم کبھی ظاہر نہیں ہو سکتے تھے اگر سورج اور چاند کا وجود نہ ہوتا.اگر سورج اور چاند نہ ہوتے تو دنوں اور سالوں کا اندازہ ہی نہ ہو سکتا اس لئے کہ اندازہ اور فاصلہ معلوم کرنے کے لئے کسی مستقل چیز کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے.جیسے پٹواری حساب لگاتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں زمین فلاں کنوئیں سے اتنے کرم کے فاصلے پر ہے یا فلاں درخت سے اتنے کرم کے فاصلے پر ہے.پس چونکہ کسی مستقل چیز کے بغیر فاصلہ کا معلوم کرنا ناممکن ہوتا ہے اس لئے اگر سورج اور چاند نہ ہوتے تو سالوں اور دنوں کا اندازہ بھی نہ ہو سکتا.اسلام نے اپنی عبادات میں سورج اور چاند دونوں سے وقت کے اندازے کئے ہیں.مثلاً دن بھر کی نمازوں کے اوقات اور روزہ کی ابتداء اور اس کی افطاری وغیرہ کا تعلق شمسی نظام کے ساتھ ہے.لیکن جہاں عبادات کسی خاص مہینہ سے تعلق رکھتی ہیں وہاں قمری نظام سے کام لیا گیا ہے جیسے رمضان اور ایام حج کے لئے قمری مہینوں کو اختیار کیا گیا ہے تاکہ دونوں عبادتیں سال کے ہر حصہ میں چکر کھاتی رہیں.اور ایک مومن فخر کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ اس نے سال کے ہر حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے.مثلاً رمضان کا انحصار چونکہ قمری مہینوں پر ہے.اس لئے۳۶ سال میں ایک دور ختم ہو جاتا ہے اور رمضان کبھی جنوری میں آجاتا ہے اور کبھی فروری میں کبھی مارچ میں اور کبھی اپریل میں اس طرح سال کے ۳۶۵ دنوں میں سے ہر دن ایسا ہوتا ہے جس میں انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے لیکن اگر شمسی مہینوں پر روزے مقرر ہوتے تو اگر ایک دفعہ جنوری میں روزے آتے تو پھر ہمیشہ جنوری میں ہی روزے رکھنے پڑتے اور اس طرح عبادت کو وسعت حاصل نہ ہوتی.پس عبادت کو زیادہ وسیع کرنے کے لئے اور اس غرض کے لئے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لحظہ کے متعلق کہہ سکے کہ وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گذارا ہے عبادت کا انحصار قمری مہینوں پر رکھا گیا ہے لیکن سال کے اختتام یا اس کے شروع ہونے کے لحاظ سے انسانی دماغ سورج سے زیادہ تسلی پاتا ہے.بہر حال قمری اور شمسی دونوں نظام حساب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے وہ چاند کے مہینوں سے ہی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ شمسی نظام سے تعلق رکھنے والے حسابات ان کی علمی استعداد سے بالا ہوتے ہیں.وَلَیْسَ الْبِرَّ بِاَنْ تَاْتُواالْبُیُوْتَ مِنْ ظُھُوْرِھَا کہتے ہیں اسلام سے پہلے عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ حج کے لئے احرام باندھ لیتے اور اس دوران میں انہیں گھر آنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ دروازوں سے آنے کی بجائے گھروں کی پشت سے دیوار پھاند کر آتے تھے(بخاری کتاب التفسیر سورة البقرة باب قولہ لیس البر بان تاتوا البیوت...)
Page 229
ہو سکتا ہے کہ یہ آیت اسی کے متعلق ہو کہ تم ایسا نہ کرو مگر میرے نزدیک چونکہ اس آیت سے پہلے گھروں کی پشت سے داخل ہونے کا کوئی ذکر نہیں اس لئے اس آیت کے یہ معنیٰ نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت سے داخل نہ ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کو سر انجام دینے کے جو صحیح طریق مقرر کئے گئے ہیں تم ان سے کام لو ورنہ تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو گی.چنانچہ دیکھ لو اس سے پہلے یہ سوال بیان کیا گیا ہے کہ رمضان میں تو ہم نے مشقت برداشت کی اور خدا تعالیٰ ہمیں مل گیا.اب ہمیں بتایا جائے کہ باقی مہینوں میں ہم نفس کشی کے لئے کیا کریں اور کون کون سے طریق اختیار کریں خدا تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری خواہش تو نیک ہے مگر یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ نہیں کہ زیادہ تکلیف اٹھا ئو بلکہ حقیقی ذریعہ یہ ہے کہ جو طریق ہم نے نیکی میں ترقی کرنے کے تمہیں بتائے ہوئے ہیں تم ان پر عمل کرو.تمہیں خود بخود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائےگا.اور اگر تم ایسا نہ کرو توتمہاری مثال ایسی ہی ہو گی جیسے کوئی آقا اپنے ملازم کو بلائے اور وہ دیر کر کے آئے تو پوچھے تم دیر کر کے کیوں آئے ہو؟ اس پر وہ کہہ دے کہ دروازے سے نہیں آیا بلکہ دیوار پھاند کر آیا ہوں اور مجھے دیوار پھاند نے میں بہت دیر لگ گئی تھی اس لئے میں جلد ی نہیں پہنچ سکا.اگر وہ یہ جواب دے تو کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ اس جواب سے اس کا آقا خوش ہو جائےگا اور اُسے انعام دےگا اور کہے گا کہ چونکہ یہ دیوار پھاند کر آیا ہے اور اس نے بڑی مشقت برداشت کی ہے اس لئے اسے ترقی دی جائے؟ اسی طرح خواہ مخواہ مشقت اُٹھا کر اپنی طرف سے نئی نئی راہیں ایجاد کرنا اور ان پر اپنا وقت ضائع کرنا اور اپنے قویٰ کو نقصان پہنچانا کوئی نیکی نہیں.نیکی یہ ہے کہ لوگ اپنے آسمانی آقا کی آواز پر لبیک کہیں اور اس راستہ کو اختیار کریں جو شریعت نے ان کے لئے قائم کر دیا ہے غرض اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ طریق جو میں نے تمہیں بتائے ہوئے ہیں اگر ان کے ذریعہ سے تم میرے پاس آئو گے تو مجھ تک پہنچ سکو گے اور اگر اور ذرائع عمل میں لائو گے اور ان میں تمہیں محنت بھی زیادہ کرنی پڑے تو یہ زیادہ محنت کرنا تمہیں خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچائےگا.جیسا کہ ہندوئوں میں سے بعض اُلٹے لٹکے رہتے ہیں بعض اپنے ہاتھ کھڑے رکھ کر خشک کر لیتے ہیں.مگر انہیں خدا تعالیٰ کی کوئی رضا حاصل نہیں ہوتی.اس کے مقابلہ میں مسلمان بھی عبادتیں کرتے ہیں جو مشقت میں ان سے بہت کم ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ رضائے الٰہی کو حاصل کر لیتے ہیں.افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی فیج اعوج کے دور میں بڑی بڑی مشقتیں اپنے نفس پر وارد کیں اور وہ غلط راستہ پر چلنے لگے.بیسیوں قسم کی چلّہ کشیاں تھیں جو انہوں نے اختیار کر لیں اور بیسیوں قسم کے ذکر تھے جو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لئے.اگر مسلمان اپنے آپ کو ان مشقتوں میں ڈالنے کی بجائے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے تو وہ
Page 230
قرب الٰہی کی ان منازل کو دنوں میں طے کر لیتے جنہیں وہ سالوں میں بھی طے نہ کر سکے بلکہ ان ریاضتوں کے نتیجہ میں ان میں سے کئی مسلول اور مدقوق ہو کر مر گئے.کئی دیوانے ہو گئے اور کئی مر گی کا شکار ہو گئے.وَ اْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.اس میں بتایا کہ کامیابی ہمیشہ ابواب ہی کے ذریعہ آنے سے ہوا کرتی ہے.اگر تم ایسا نہیں کرتے اور دروازوں میں سے داخل ہونے کی بجائے دیواریں پھاند کر اندر داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی.مثلاً لڑائی کے زمانہ میں اگر تم ہتھیاروں سے کام لینا نہ سیکھو اور جنگی فنون کی تربیت نہ لو بلکہ یونہی سینہ تان کر دشمن کے سامنے چلے جائو.تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے.لیکن اگر چھوٹی سے چھوٹی تلوار بھی تمہارے پاس ہو یا تمہیں لاٹھی چلانا ہی آتا ہو تو تم قوم کے لئے مفید وجود بن سکتے ہو.پس کامیابی کے لئے ان ذرائع اور اسباب کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کئے ہوئے ہیں.ورنہ اسے ناکامی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا.پھر وَ اتَّقُوا اللّٰهَ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ذرائع اور اسباب کو نظر انداز کرنا اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے نظام کی ہتک کرنا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور ہر چیز کے حصول کے جو طریق اللہ تعالیٰ نے مقرر کئے ہوئے ہیں انہی کے مطابق چلو اپنے پاس سے نئے نئے طریق وضع نہ کرو.مثلاً رمضان کے مہینہ میں بیشک روزے رکھنا ایک بڑی نیکی ہے لیکن اگر اسی پر قیاس کرتے ہوئے کوئی شخص کسی اور مہینہ میں بھی تیس تیس روزے رکھنے شروع کر دے اور سمجھے کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر لےگا تو وہ ایسا ہی ہو گا جیسے کوئی دروازہ سے داخل نہ ہو بلکہ نقب لگا کر داخل ہو اور اندر جا کر کہے کہ دیکھئے میں کیسی مشقّت اٹھا کر آپ تک پہنچا ہوں.ایسے شخص کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا بلکہ ہر شخص اسے ملامت کرے گا اور اس کے فعل کو قابلِ مذمت قرار دےگا.وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا١ؕ اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں.اور کسی پر زیادتی نہ کرو.اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ۰۰۱۹۱ (اور یاد رکھو )کہ اللہ (تعالیٰ) زیادتی کرنے والوں سے ہر گز محبت نہیں کرتا.تفسیر.اب اللہ تعالیٰ نے دینی جنگوں کے احکام بیان کرنے شروع کئے ہیں.چنانچہ اس پہلی آیت میں
Page 231
ہی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام شرائط بیان کر دی ہیں جن کو مذہبی جنگوں میں ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے.چنانچہ فرماتا ہے اے مسلمانو! ان کفار سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں تم بھی محض اللہ تعالیٰ کی خاطر جس میں تمہارے اپنے نفس کا غصہ یا نفس کی ملونی شامل نہ ہو جنگ کرو اور یاد رکھو کہ جنگ میں بھی کوئی ظالمانہ فعل نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بہرحال پسند نہیںکرتا.اس آیت سے ظاہر ہے کہ جس جنگ کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے وہ صرف وہی ہے جو اوّل فی سبیل اللہ ہو.یعنی ذاتی لالچوں ، ذاتی حرصوں ملک کے فتح کرنے کی نیت یا اپنے رسوخ کو بڑھانے کی نیت سے نہ ہو بلکہ صرف خدا تعالیٰ کے لئے ہو یعنی ان مشکلات کو دور کرنے کے لئے ہو جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اور اس کے دین کے راستہ میں پیدا کی گئی ہوں.اگر وہ دینی جنگ نہیں تو اُسے فی سبیل اللہ نہیں کہا جا سکتا.مسیحی مصنف فی سبیل اللہ کے الفاظ سے دھوکہ کھاتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد زبردستی مسلمان بنانے کے ہوتے ہیں.حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اس کے معنے تو یہ ہیں کہ صرف وہی جنگ جائز ہے جو خدا تعالیٰ کے منشاء کے مطابق اور اس کی رضا چاہنے کے لئے ہو.چنانچہ اسی قسم کے الفاظ اسی سورۃ کی آیت نمبر۲۶۳ میں بھی استعمال کئے گئے ہیں.جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ١ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.یعنی جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ کسی رنگ میں احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں ان کے رب کے پاس ان کے اعمال کا بدلہ محفوظ ہے اور نہ تو انہیں کسی قسم کا خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوںگے.اس آیت میں جو فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں انہی کی تشریح آیت نمبر۲۶۶ میں ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ یعنی وہ لوگ اپنے اموال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں.اسی طرح لسان العرب جو لغت کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ کُلُّ مَا اَمَرَ اللّٰہُ بِہٖ مِنَ الْخَیْرِ فَھُوَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَیْ مِنَ الطُّرُقِ اِلَی اللّٰہِ یعنی ہر نیکی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے.اور نہایۃ میں لکھا ہے وَسَبِیْلِ اللّٰہِ عَامٌّ یَقَعُ عَلٰی کُلِّ عَمَلٍ خَالِصٍ سُلِکَ بِہٖ طَرِیْقُ التَّقَرُّبِ اِلَی اللّٰہِ تَعَالٰی بِاَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَاَنْوَاعِ التَّطَّوُّعَاتِ یعنی سَبِیْلِ اللّٰہ ایک عام اصطلاح ہے جس کا اطلاق ہر ایسے عمل نیک پر ہوتا ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہو.خواہ وہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعہ ہو یا نوافل یا دوسری نیکیوں میں حصہ لینے کے ذریعہ ہو.
Page 232
پس قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ کے یہ معنے نہیں کہ تم دوسروں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لئے جنگ کرو.بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ جب کوئی قوم دین کے بارہ میں تم سے جنگ کرے اور تمہارا مقدس مذہب تم سے زبردستی چھڑانا چاہے تو اس وقت تمہارا فرض ہے کہ تم محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور دینی مشکلات کو دور کرنے کے لئے دشمن سے جنگ کرو.پس اس میں کفار کو زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ کفار کے اس جبر کو دور کرنے کا ذکر ہے جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے لئے مذہبی آزادی تک باقی نہیں رہی تھی.دوسری شرط اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کی ہے کہ لڑائی صرف انہی لوگوں سے جائز ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں ہتھیار اُٹھا چکے ہوں.جیسا کہ یُقَاتِلُوْ نَکُمْ کے الفاظ اس پر شاہد ہیں.تیسری شرط جو یُقَاتِلُوْ نَکُمْ میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ تمہارے لئے صرف انہی سے جنگ کرنا جائز ہے جو تم سے لڑتے ہیں.یعنی جو لوگ باقاعدہ سپاہی نہیں اور لڑائی میں عملاً حصہ نہیں لیتے جیسے بچے بوڑھے عورتیں وغیرہ ان کو مارنا یا ان سے لڑائی کرنا جائز نہیں گویا سول آبادی کو لڑائی کے دائرہ سے کلیتہً باہر رکھا گیاہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کی جو تشریح فرمائی ہے وہ ان احکام سے ظاہر ہے جو آپ اس وقت دیتے تھے جب آپ کسی کو کمانڈر بنا کر جنگ پر بھجواتے تھے.چنانچہ مسلم جلد ۲کتاب الجہاد میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر یا دستہ فوج کا کسی کو افسر بنا کر بھجواتے تھے تو آپ اُسے اور دوسرے مسلمانوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اور پھر فرماتے اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰہِ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ.اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اللہ تعالیٰ کی خاطر جنگ کے لئے جائو.قَاتِلُوْ امَنْ کَفَرَ بِاللّٰہ ِ اس شخص کے ساتھ جنگ کر و جو اللہ تعالیٰ کا کفر اختیار کرے.اس کے یہ معنے نہیں کہ تم کافر سے لڑو بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ جس شخص سے تمہاری لڑائی ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تم نے اس سے لڑنا نہیں تمہیں لڑائی کی صرف اس وقت تک اجازت ہے جب کفر باللہ کی شرط موجود ہے.اگر کسی شخص نے لڑائی تو شروع کی مگر جب تمہارا لشکر پہنچا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اسلام اختیار کرتا ہوں تو بس لڑائی ختم ہو جائےگی.وَلَا تَغُلُّوْا اور قطعی طور پر خیانت سے کام نہ لو.وَلَا تَغْدِرُوْا اور بد عہدی نہ کرو.دھوکہ بازی سے کام نہ لو.اگر تم اپنے دشمن سے کوئی وعدہ کر لو تو بعد میں اُسے کسی بہانہ سے توڑنے کی کوشش نہ کرو.وَلَا تُمَثِّلُوْا اور تم مثلہ نہ کرو یعنی کفار اپنی رسم کے مطابق اگر مسلمان مقتولین کے ناک کان بھی کاٹ دیں تو بھی تم ان کے مُردوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو.وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِیْدًا اور کسی نابالغ بچے کو نہ مارو کیونکہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوا.(مسلم کتاب الجھاد باب تأمیر الامام الامراء علی البعوث......) سیرتِ حلبیہ میں اس کے
Page 233
علاوہ بعض اور نصائح بھی درج ہیں.اس میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو جنگ پرجاتے وقت یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لَاتَقْتُلُوْا اِمْرَءَ ۃً.کسی عورت کو نہیں مارنا وَلَا کَبِیْرًا فَانِیًا اور کسی بڈھے شخص کو بھی نہیں مارنا.وَلا مُعْتَزِلًا بِصَوْمَعَۃٍ.اور عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں مارنا.کیونکہ گووہ ایک ایسی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو تمہاری مخالف ہے مگر وہ خدا کا نام لیتے ہیں پھر فرماتے وَلَا تَقْرَبُوْا نَخْلًا.کسی کھجور کے درخت کے قریب بھی نہ جانا یعنی کھجور کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی نہ کرنا.کیونکہ اس سے ان کے رزق پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا حملہ ان کے حملے کو دور رکھنے کی نیت سے ہے ان کو مستقل تباہ کرنے کی غرض سے نہیں.وَلَا تَقْطَعُوْا شَجَرًا بلکہ کوئی درخت بھی نہ کاٹنا کیونکہ وہ غریبوں اور مسافروں کو سایہ دینے کے کام آتا ہے اور تم لڑنے کے لئے جارہے ہو اس لئے نہیں جا رہے کہ وہ قوم سایہ سے بھی محروم ہو جائے.وَلَا تَھْدِ مُوْا بِنَاءً.اسی طرح عمارتوں کو مت گِرائو.قلعہ کا انہدام ایک علیٰحدہ چیز ہے.وہ جنگ کے حملے کو روکنے کے لئے ہوتا ہے.مگر یہ جائز نہیں کہ کسی ملک کے باشندوں کو بے گھر کر دیا جائے اورا ن کے مکانوں کو گرادیا جائے یا انہیں آگ لگا دی جائے.اسی طرح آپ کی دوسری ہدایات میں ہے کہ ملک میں ڈر اور ہراس پیدا نہ کیا جائے.دنیوی حکومتیں جب کسی ملک میں داخل ہوتی ہیں تو اندھا دھند مظالم شروع کر دیتی ہیں محض اس لئے کہ حکومت کا رعب قائم ہو جائے.مگر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مفتوحہ ممالک میں جائو تو ایسے احکام جاری کرو جن سے لوگوں کو آسانی ہو تکلیف نہ ہو(السیرۃ الحلبیۃ باب سرایاہ ؐ و بعوثہ).اور فرمایا جب لشکر سڑکوں پر چلے تو اس طرح چلے کہ عام مسافروں کا راستہ نہ رکے.ایک صحابیؓ کہتے ہیں ایک دفعہ لشکر اس طرح نکلا کہ لوگوں کے لئے اپنے گھروں سے نکلنا اور راستہ چلنا مشکل ہو گیا اس پر آپ نے منادی کروائی کہ جس نے مکانوں کو بند کیا یاراستہ روکا اس کا جہاد جہادہی نہیں رہےگا.غرض اسلام کہتا ہے کہ تم کو جنگ میں عورتوں کے مارنے کی اجازت نہیں تم کو بچوں کے مارنے کی اجازت نہیں.تم کو بڈھوں کے مارنے کی اجازت نہیں.تم کو بد عہدی کر نے کی اجازت نہیں.تم کو دھوکا دینے کی اجازت نہیں.تم کو مقتولین کے ناک کان کاٹنے کی اجازت نہیں.تم کو پادریوں اور پنڈتوں اور گیانیوں کو مارنے کی اجازت نہیں.تم کو کوئی باغ اور درخت کاٹنے کی اجازت نہیں.تم کو کوئی عمارت گرانے کی یا اُسے آگ لگانے کی اجازت نہیں اور اگر کبھی ان ہدایات کی خلاف ورزی ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا.عرب کے دستور کے مطابق عورتیں بھی لڑائی میں شامل ہوتی تھیں اور چونکہ وہ دوسروں کو قتل کرتی تھیں لازماً وہ خود بھی قتل کی جاتی تھیں مگر ایک موقعہ پر ایک لڑائی کے بعد جب ایک عورت کی لاش آپ نے دیکھی تو آپ کے چہرے پرغم
Page 234
اور غصہ کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا یہ فعل اسلامی تعلیم کے خلاف ہوا ہے (مسلم کتاب الجہاد والسیر باب تحریم قتل النساء و الصبیان فی الحرب ) اُحد کی جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پیش کی اور فرمایا یہ تلوار میں اس شخص کو دوںگا جو اس کا حق ادا کرنے کا وعدہ کرے.بہت سے لوگ اس تلوار کو لینے کے لئے کھڑے ہوئے آپ ابودجانہؓ انصاری کو وہ تلوار دی.لڑائی میں ایک جگہ مکہ والوں کے کچھ سپاہی ابودجانہؓ پر حملہ آور ہوئے.جب آپ ان سے لڑ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سپاہی سب سے زیادہ جوش کے ساتھ لڑائی میں حصہ لے رہا ہے.آپ نے تلوار اُٹھائی اور اس کی طرف لپکے لیکن پھر اس کو چھوڑ کر واپس آگئے.آپ کے کسی دوست نے پوچھا.آپ نے اُسے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے جواب میں کہا.میں جب اس کے پاس گیا تو اس کے منہ سے ایک ایسا فقرہ نکلا جس سے مجھے معلوم ہوگیا کہ وہ مرد نہیں عورت ہے ان کے ساتھی نے کہا بہرحال وہ سپاہیوں کی طرح فوج میں لڑ رہی تھی.پھر آپ نے اُسے چھوڑا کیوں؟ ابودُجانہ ؓ نے کہا میرے دل نے برداشت نہ کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار کو ایک کمزور عورت پر چلائوں(السیرة النبویة ابن ہشام غزوةاحد ).غرض آپ عورتوں کے ادب اور احترام کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھے جس کی وجہ سے کفار کی عورتیں زیادہ دلیری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں مگر پھر بھی مسلمان ان باتوں کی برداشت کرتے چلے جاتے تھے.صرف ایک ہی عورت تھی جس نے شروع سے لےکر آخر تک اسلام کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا اور مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹ لینے میں بہت مشہور تھی یعنی ہندہ.فتح مکہ کے وقت آپ نے صرف اس کے قتل کا حکم دیا مگر وہ باقی عورتوں کے ساتھ آئی اور مسلمان ہو گئی اور پھر آپ نے اُسے بھی کچھ نہیں کہا.کیونکہ آپ نے فرمایا توبہ نے اس کے سارے گناہوں کو دھو دیا ہے(السیرة الحلبیۃ باب ذکر مغازیہ ؐ فتح مکۃ شرفھا اللہ تعالیٰ).چوتھی شرط وَ لَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ کے الفاظ میں یہ بیان فرمائی کہ باوجود دشمن کے حملہ میں ابتداء کرنے کے لڑائی کو صرف اس حد تک محدود رکھنا چاہیے جس حد تک دشمن نے محدود رکھا ہے اور اسے وسیع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے.نہ علاقہ کے لحاظ سے اور نہ ذرائع جنگ کے لحاظ سے اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ گذر جانے والوں سے محبت نہیں کرتا یا یوں کہو کہ جو لوگ حد سے گذر جانے والے ہوں وہ کبھی خدا تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتے.حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص طبعی طور پر اللہ تعالیٰ سے محبت کر ہی نہیں سکتا.کیونکہ وہ حق کا مطالبہ کرنے میں حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے.مثلاً کسی کو غصہ آ گیا اور اس نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو اب یہ ایک غلطی تو ہے جس کی اُسے سزا ملنی چاہیے مگر یہ سزا اتنی ہی ہو سکتی ہے کہ ہم اُسے بلائیں اور ڈانٹ دیں کہ تم نے فلاں کو
Page 235
تھپڑ کیوں مارا لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس شخص سے قصور سر زد ہوا ہو جب تک وہ اس کا قیمہ نہ کر لیں ان کی تسلی ہی نہیں ہوتی.اور پھر یہیں تک بس نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں کہ جب وہ اگلے جہان میں پہنچے تو وہاں بھی خدا اس کو دوزخ میں ڈالے اور اُسے ایسا عذاب دے جو کسی اور کو نہ دیا گیاہو حالانکہ خدا بڑا رحیم و کریم ہے وہ حد سے گذرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور نہ حد سے گذرنے والا خدا تعالیٰ سے محبت کر سکتا ہے.اس زمانہ میں بڑی بڑی طاقتیں اس بات کی مدعی ہیں کہ انہوں نے عدل و انصاف کو کمال تک پہنچا دیا ہے مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لڑائی میں ہر قسم کے جھوٹ اور ظلم اور دھوکا اور فریب سے کام لیتی ہیں اور جب تک دشمن کو پیس نہ لیں ان کے دل کی آگ ہی نہیں بجھتی کہیں گیسیں استعمال کی جاتی ہیں تو کہیں قیدیوں کو پکڑ کر لڑائی کے وقت اپنے آگے رکھا جاتا ہے.اسی طرح اور کئی ظالمانہ طریق اختیار کئے جاتے ہیں.مثلاً یہ بھی اعتداء میں داخل ہے کہ دشمن کا لباس پہن کر یا اس کا نشان دکھا کر حملہ کر دیا جائے یا صلح کے بہانہ سے حملہ کیا جائے یہ تمام امور ناجائز اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہیں.بہرحال اوپر کی دونوں آیات سے مندرجہ ذیل چھ امور کا استنباط ہوتا ہے.پہلی بات یہ مستنبط ہوتی ہے کہ غیر شرعی طریق سے جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے کیونکہ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں جن میں داخل ہونےکا تم کو ہر وقت اور پورا اختیار ہے ان میں بھی اگر تم دیواریں پھاند پھاند کر داخل ہو تو یہ امر خدا تعالیٰ کے نزدیک نیکی نہیں سمجھا جا ئےگا.اس مثال سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لئے ایک رستہ بنایا ہے.اگر تو انسان اس رستہ سے اس کام کو کرتا ہے تو اس کا کام نیکی قرار دیا جائےگا.لیکن اگر کام نیک ہو مگر اس کے کرنے کا طریق غلط ہو تو پھر وہ عمل نیک نہیں رہے گا.مثلاً نماز ایک نیکی ہے لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے یا پہلے نماز پڑھ لے بعد میں وضو کرے یا بے وقت نماز پڑھے تو باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھے گا جو ایک عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکے گا بلکہ ایک بدی کا مرتکب ہو گا.بعینہٖ اسی طرح اظہار غضب ہے.اللہ تعالیٰ نے غیرت کو ایک نیکی قرار دیا ہے.اللہ تعالیٰ خود بھی نہایت غیرت مند ہے اور وہ بری باتوں پر اظہار غضب بھی کرتا ہے لیکن غیرت کے جائز موقعہ پر بھی اگر کوئی شخص غیرت کا اظہار غلط طریق پر کرے اور شریعت جس موقعہ پر غضب کی اجازت دیتی ہے غضب کو اسی موقعہ پر ظاہر کرے لیکن اس کا طریق بدل دے تو یہ گناہ ہو جائے گا مثلاً شریعت اظہار غیرت یا اظہار غضب کا یہ طریق بتائے کہ اس جگہ سے مومن اُٹھ جائے مگر مومن اس جگہ سے بجائے اُٹھ جانے کے لڑنے لگے تو شریعت اس مومن کو بھی گنہگار قرار دے گی.دوسری بات جو اس آیت سے مستنبط ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی تقویٰ کا نام ہے.یعنی نیک کام کو نیک راہ سے بجا
Page 236
لانا.پس مومن کا فرض ہے کہ ہر گھر میں اس کے دروازہ سے داخل ہو یعنی ہر نیک کام کے لئے خدا تعالیٰ نے جو طریق تجویز کیا ہے اس طریق سے اس کام کو کرے.جو شخص اس طریق سے کام نہ کرے وہ نیک نہیں کہلا سکتا.تیسری بات جو مذکورہ بالا آیات سے مستنبط ہوتی ہے یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اوپر کے بتائے ہوئے راستہ میں ہےبلکہ خود انسان کی کامیابی بھی اسی راہ پر چلنے میں ہے.چنانچہ فرماتا ہے لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ یعنی یہ حکم ہم نے یونہی نہیں دیئے.تمہاری ترقی اور کامیابی بھی اسی طریق سے وابستہ ہے.کامیابی کا اس امر کے ساتھ وابستہ ہونا ایک ظاہر امر ہے جو راستے کسی عمارت میں داخل ہونے کے ہوں جب انسان ان راستوں سے داخل ہو تبھی وہ بغیر کسی تکلیف کے اپنے مدعا کو پاسکتا ہے.اگر ان راستوں کو چھوڑ کر دیواریں پھاندنی شروع کر دے تو اس کی تکلیف بڑھ جائےگی اور اس کی حماقت کی بھی لوگ شکایت کرنے لگیں گے.چوتھی بات اس آیت سے یہ مستنبط ہوتی ہے کہ کسی شخص پر جارحانہ حملہ کرنا خلاف شریعت ہے.چنانچہ آیت مذکورہ بالا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ.یہ تو تمہارے لئے جائز ہے کہ اگر کوئی تم پر قاتلانہ حملہ کرے تو تم اپنا بچائو کرو.لیکن تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم خود کسی پر جا کر حملہ کرو.پانچواں استنباط ان آیات سے یہ ہو تا ہے کہ دفاع بھی وہ جائز ہے جو مقررہ حدود کے اندر ہو.یعنی دفاع میں بھی انسان پوری طرح آزاد نہیں.اس کے لئے بھی قیود اور شرائط ہیں اور ان قیود اور شرائط سے آزاد ہو کر جو دفاع کیا جائے وہ بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے.مثلاً کوئی شخص کسی کو تھپڑ مارے تو جس شخص کو تھپڑ مارا گیا ہے اس کے لئے یہ درست نہ ہو گا کہ اس تھپڑ کی سزا کے لئے دوسرے شخص کا سر پھوڑ دے.چھٹی بات اس آیت سے یہ مستنبط ہوتی ہے کہ اگر کوئی ان قیود کو توڑے تو باوجود مظلوم ہونے کے خدا تعالیٰ کی نظروں سے وہ گر جائےگا.کیونکہ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ اگر تم دفاع میں بھی اعتداء سے کام لو اور خدا تعالیٰ کی مقررہ قیود کو نظر انداز کر دو تو تم اللہ تعالیٰ کی محبت کھو بیٹھو گے اور اس کی نصرت تم سے جاتی رہے گی.وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ۠ وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اور جہاں بھی ان (ناحق لڑنے والوں )کو پاؤ انہیں قتل کرو.اور تم (بھی ) انہیں اس جگہ سے نکال دو جہاں سے اَخْرَجُوْكُمْ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ١ۚ وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ انہوں نے تمہیں نکالا تھا.اور (یہ) فتنہ قتل سے( بھی ) زیادہ سخت(نقصان دہ) ہے.اور تم ان سے مسجد حرام
Page 237
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ١ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ کے قرب(وجوار) میں(اس وقت تک) جنگ نہ کرو جب تک وہ (خود) تم سے اس میں جنگ (کی ابتداء) فَاقْتُلُوْهُمْ١ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ۰۰۱۹۲فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ نہ کریں.اور اگر وہ تم سے (وہاں بھی) جنگ کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو.ان کافروں کی یہی سزا ہے.پھر اگر وہ باز اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰۰۱۹۳ آجائیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا (اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے.حلّ لُغات.اَلْفِتْنَۃُ کے معنے ہیں (۱) اَلْعَذَابُ عذاب (۲) اَلْاِ بْتِلَاء ابتلاء (۳) اِخْتِلَافُ النَّاسِ فِی الْآٰ رَائِ وَمَا یَقَعُ بَیْنَھُمْ مِنَ الْقِتَالِ وہ لڑائی جو اختلافِ آراء کی وجہ سے لوگوں میں پیدا ہو.(اقرب) تفسیر.مخالفین اسلام کے نزدیک اس آیت میںمسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جہاں کوئی کافر ملے اُسے مار ڈالو.مگر اس میں ہر گز یہ نہیں کہا گیا کہ جہاں کوئی کافر ملے اسے تہ تیغ کر دوبلکہ اس جگہ وَ اقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ۠کے حکم کے ماتحت صرف وہ کفار آتے ہیں جن کا پہلے ذکر آچکا ہے اور جنہوں نے مسلمانوں سے عملاً جنگ شروع کر دی تھی ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھنے میں نہ اخلاقاً کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ شرعاً.اور حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ۠ میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی تمہاری اور ان کی جنگ کے ذریعہ سے مٹھ بھیڑ ہو جائے وہاں تم ان سے جنگ کرو.یہ نہیں کہ اِکّا دُکّا ملنے پر حملہ کرتے پھرو بلکہ تمہاری جنگ صرف باقاعدہ فوج کے ساتھ ہونی چاہیے.خواہ وہ فوج ہو جس نے مقابلہ میں ابتداء کی ہے یا اُسی فوج کا کوئی دوسرا حصہ ہو جو اس کی مدد کر رہا ہو.پھر فرمایا وَ اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ اور تم بھی انہیں اس جگہ سے نکال دو جس جگہ سے انہوں نے تم کو نکالا ہے.ان الفاظ میں یہ پیشگوئی مخفی تھی کہ ایک زمانہ میں مسلمان ایسی طاقت حاصل کرلیں گے کہ وہی مقام جہاں سے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو نکلنے پر مجبور کیا تھا.اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو فاتحانہ طور پر داخل کرے گا.اور یا تو مسلمان کفار کے مظالم کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے اور یا کفار مسلمانوں کی منتیں کرتے
Page 238
اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے دکھائی دیںگے.اسی غلبہ کی طرف سورۃ توبہ میں بھی بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ (التوبۃ:۱)کے الفاظ میں اشارہ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں مکی نبی ہوں جس کی پیشگوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی مگر یہ تو مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا ہے.پھر یہ پیشگوئی کس طرح پوری ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ نے عرب کو فتح کر کے جس کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہیں آسکتے تھے اس اعتراض کو دور کر دیا ہے اور آپ اور آپ کے ساتھی اس الزام سے بری ہو چکے ہیں اس کے بعد فرمایا فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ (التوبۃ:۲).تم ملک عرب میں چار مہینے تک پھر کر دیکھ لو اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے یعنی اس سفر کے نتیجہ میں تمہیں اقرار کرنا پڑے گا کہ اسلام عرب کے کونہ کونہ پر غالب آچکا ہے.اور تمہارے تمام اعتراضات غلط ثابت ہو چکے ہیں.پس اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْمیں اسی غلبہ کی پیشگوئی ہے اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح انہوں نے تم کو ظالمانہ طور پر ملک سے نکالا ہے اسی طرح تم بھی ان کا تصرف وہاں سے ہٹا دو.اس جگہ اَخْرِجُوْهُمْ سے ان کا نکالنا مراد نہیں.بلکہ ان کے تصرف کو مٹانا مرا دہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو وہاں سے نکالا نہیں بلکہ ان کی اولاد کو خود آپ نے مکہ میں رہنے کی اجازت دی.چنانچہ ابو جہل جو سب سے بڑا مشرک اور دشمن اسلام تھا فتح مکہ کے موقعہ پر اس کے بیٹے عکرمہ نے بھاگ کر ایبے سینیا جانے کا ارادہ کیا اور وہ مکہ سے چلا بھی گیا مگر اس کی بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لی اور وہ مکہ میں آزادانہ طور پر رہنے لگ گیا(السیرۃ النبویة لابن ہشام ،ذکر فتح مکۃ).پس چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اس کی تشریح کر دی ہے اس لئے اَخْرِ جُوْ ھُمْ میں کفار کے جبری نکالنے کا کوئی حکم نہیں بلکہ وہاں سے ان کا تصرف دور کرنے کا ذکر ہے.یا زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو نکالنے کا حکم ہے جو شریر ہوں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھنے والے ہوں اور ایسے لوگوں کو دنیا کی ہر حکومت نکالتی ہے اور اس میں کسی قسم کا حرج نہیں سمجھتی.وَالْفِتْنَۃُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.پھر فرماتا ہے یاد رکھو قتل اور لڑائی کی نسبت دین کی وجہ سے کسی کو فتنہ میں ڈالنا زیادہ خطرناک گناہ ہے پس تم ایسا طریق مت اختیار کرو.کیونکہ یہ بے دین لوگوں کا کام ہے.اس جگہ فتنہ سے مراد وہی دورِ آزمائش ہے جس میں سے مسلمان گذر رہے تھے اور جس کا اس سے پہلے ان الفاظ میں ذکر آچکا ہے کہ کفار بلاوجہ محض دینی اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کو مارتے اور انہیںاپنے گھروں سے
Page 239
نکالتے ہیں.فرماتا ہے دین کی وجہ سے لوگوں کو دکھ دینا اور انہیں ان کے گھروں سے نکالنا دنیوی لڑائیوں اور عام سیاسی جنگوں کی نسبت کہ جن میں قومی حقوق وغیرہ کا سوال پیدا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہولناک جرم ہے کیونکہ دنیا دین کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی.اور یہ بھی کہ فتنہ یعنی مومنوں کی تعذیب اس غرض سے کہ وہ ا پنے دین کو چھوڑ دیں قتل سے بڑھ کر ہے.کیا بلحاظ اس کے کہ دین کے معاملہ میں جان کچھ حقیقت نہیں رکھتی اور کیا بلحاظ اس کے کہ ایسے ظلم کا نتیجہ نہایت خطرناک فساد ہوتا ہے اور ذہنی آزادی جاتی رہتی ہے اور دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے.پس فرمایا کہ ان کو قتل کرنا کوئی ظلم نہیں کیونکہ قتال تو قتال سے ہی جائز ہو جاتا ہے اور یہ لوگ تو قتال سے بڑھ کر مذہبی دست اندازی اور مذہب کی خاطر تعذیب سے بھی کام لیتے ہیں جو قتال سے بڑھ کر ہے.پھر وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ بیشک قتل ایک بہت بُرا فعل ہے.مگر فتنہ پیدا کرنا اس سے بھی زیادہ بُری چیز ہے کیونکہ اس سے لاکھوں بلکہ کروڑوں جانیں ضائع چلی جاتی ہیں.قتل کرنے سے تو صرف ایک یا چند جانیں ضائع ہوتی ہیں لیکن ایک فتنہ پر داز شخص بعض دفعہ ایسی بات کر دیتا ہے جس سے قومیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں اور جماعتوں میں تفرقہ اور شقاق پیدا ہو جاتا ہے.فتنہ باز لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو معمولی بات کہی تھی مگر ان کا ایک معمولی بات کہنا دراصل ایک زہر ہوتا ہے جس کا دور دور تک اثر پھیلتا ہے او رپھر اس سے خطرناک لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں جن سے لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اُتر جاتے ہیں.بیشک فتنہ شروع میں چھوٹا نظر آتا ہے مگر اس کا انجام بہت بڑا ہوتا ہے.اسی لئے اسلام نے قتل سے بھی منع کیا ہے مگر فتنہ سے اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ منع کیا ہے.افسوس ہے کہ لوگ عام طور پر قتل سے تو بچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر فتنہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ جب تک لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر بُرا فعل ہے اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیںہو سکتا.وَ لَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ.اب فرماتا ہے کہ تم مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک جنگ نہ کرو جب تک کہ وہ خود جنگ کی ابتداء نہ کریں کیونکہ اس طرح حج اور عمرہ کے راستہ میں روک پیدا ہوتی ہے.فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْہاں اگر وہ خود ایسی جنگ کی ابتداء کریں تو پھر تم مجبور ہو اور تمہیں جواب دینے کی اجازت ہے.كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ.اور جو لوگ عقل اور انصاف کے احکام کو رد کر دیتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا پڑتا ہے.اس آیت میں یہ ہدایت دی گئی کہ اس امر کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ مذہبی عبادتوں اور مذہبی فرائض
Page 240
کی ادائیگی میں روکیں پیدا نہ ہوں اگر دشمن کسی ایسی جگہ پر جنگ کی طرح نہ ڈالے جہاں جنگ کرنے سے مذہبی عبادتوں میں رخنہ پیدا ہوتا ہو تو مسلمانوں کو بھی اس جگہ جنگ نہیں کرنی چاہیے.لیکن اگر دشمن خود مذہبی عبادت گاہوں کو لڑائی کا ذریعہ بنائے تو پھر مجبوری ہے.اس آیت میں اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ عبادت گاہوں کے اردگرد بھی لڑائی نہیں ہونی چاہیے.کجا یہ کہ عبادت گاہوں پر براہ راست حملہ کیا جائے یا ان کو مسمار کیا جائے.یا ان کو توڑا جائے.ہاں اگر دشمن خود عبادت گاہوں کو لڑائی کا قلعہ بنا لے تو پھر ان کے نقصان کی ذمہ داری اس پر ہے مسلمانوں پر نہیں.فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ہاں اگر انہیں ہوش آجائے اور وہ اس بات سے رُک جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے یعنی اگر دشمن مذہبی مقامات میں لڑائی شروع کرنے کے بعد اس کے خطرناک نتائج کو سمجھ جائے اور مذہبی مقام سے نکل کر دوسری جگہ کو میدان جنگ بنالے تو مسلمانوں کو اس بہانہ سے ان کے مذہبی مقاموں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کہ اس جگہ پر پہلے ان کے دشمنوں نے لڑائی شروع کی تھی بلکہ فوراً ان مقامات کے ادب اور احترام کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے حملہ کا رُخ بدل دینا چاہیے.وَ قٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ١ؕ اور تم ان سے اس وقت تک جنگ کرو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے.اور دین اللہ ہی کے لئے ہو جائے فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ۰۰۱۹۴ پھر اگر وہ باز آجائیں(تو یاد رکھو کہ) ظالموں کے سوا کسی پر گرفت (جائز) نہیں.تفسیر.فرماتا ہے چونکہ کفار تم سے لڑائی شروع کر چکے ہیں اس لئے تم بھی اس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک کہ دین میں دخل اندازی کرنے کے طریق کو وہ چھوڑ نہ دیں.اور یہ تسلیم نہ کر لیں کہ دین کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس میں جبر کرنا کسی انسان کے لئے جائز نہیں.اگر وہ یہ طریق اختیار کر لیں اور دین میں دخل اندازی سے باز آجائیں تو فوراً لڑائی بند کر دو کیونکہ سزا صرف ظالموں کو دی جاتی ہے اور اگر وہ اس قسم کے ظلم سے باز آجائیں تو پھر ان سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہو سکتا.یہ امر یاد رکھنا چا ہیے کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے اَلْفِتْنَۃُ فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اَلْفِتْنَۃُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ.مگر اس
Page 241
جگہ صرف فِتْنَۃٌ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں فتنہ کفار اور قتال کا مقابلہ کرنا تھا پس معرفہ لانا ضروری تھا اور اس جگہ مقابلہ نہ تھا پس نکرہ لایا گیا تاکہ عظمتِ فتنہ پر دلالت کرے اور اس کے معنے یہ ہیں کہ تم اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک کہ یہ عظیم الشان فتنہ دور نہ ہو جائے.بعض لوگوں نے اس کے یہ معنے کئے ہیں کہ تم یہاں تک لڑو کہ کفر باقی نہ رہے(قرطبی).لیکن یہ معنے غلط ہیں.اس جگہ فتنہ سے مراد کفر نہیں بلکہ دین میں دخل اندازی ہے جس کا سورۃ الحج کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا١ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ.ا۟لَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ١ؕ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا (الحج: ۴۰.۴۱) یعنی اس لئے کہ مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ان مسلمانوں کوجن سے دشمن نے لڑائی شروع کر رکھی ہے آج جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد کرنے پر قادر ہے.ہاں ان مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جن کو ان کے گھروں سے بغیر کسی جرم کے نکال دیا گیا.ان کا صرف اتنا ہی جرم تھا (اگر یہ کوئی جرم ہے) کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے.اور اگر اللہ تعالیٰ بعض ظالم لوگوں کو دوسرے عادل لوگوں کے ذریعہ سے ظلم سے روکتا نہ رہے تو گرجے ،عبارت گاہیں اور مسجدیں جن میں خدا تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے ظالموں کے ہاتھ سے تباہ ہو جائیں.پس دنیا میں مذہب کی آزادی قائم رکھنے کےلئے اللہ تعالیٰ مظلوموں کو اور ایسی قوموں کو جن کے خلاف دشمن پہلے جنگ کا اعلان کر دیتا ہے جنگ کی اجازت دیتا ہے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لڑائی صرف اس وقت تک جاری رکھنی چاہیے جب تک فتنہ باقی رہے.یعنی لوگ تبدیل مذہب کے لئے ایک دوسرے کو مجبور کرتے رہیں.اگر یہ حالات بدل جائیں مذہبی دست اندازی ختم ہو جائے اور دین کے معاملہ کو صرف ضمیر کامعاملہ قرار دیا جائے تو خواہ دشمن حملہ میں ابتداء کر چکا ہو سوائے دفاع کے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے.ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہؓ کرام نے بھی اس آیت کے یہی معنے سمجھے ہیں.چنانچہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص اس زمانہ میں جبکہ حضرت علی ؓاور معاویہؓ کے درمیان جنگ جاری تھی حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ کے پاس آکر کہنے لگا کہ آپ حضرت علیؓ کے زمانہ کی جنگوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے حالانکہ قرآن کریم میں صاف حکم موجود ہے کہ وَقٰتِلُوْ ھُمْ حَتّٰی لَا تَکُوْنَ فِتْنَۃٌ.انہوں نے جواب دیا کہ فَعَلْنَا عَلٰی عَھْدِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَ کَانَ الْاِسْلَامُ قَلِیْلًا فَکَانَ الرَّجُلُ یُفْتَنُ فِیْ دِیْنِہٖ اِمَّا قَتَلُوْہُ وَ اِمَّا یُعَذِّ بُوْہُ حَتّٰی کَثُرَ الْاِسْلَامُ فَلَمْ تَکُنْ فِتْنَۃٌ(بخار ی کتاب التفسیر سورة البقرة باب قولہ
Page 242
وقاتلوھم حتی لا تکون فتنۃ ) یعنی ہم نے یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پورا کر دیا ہے جبکہ اسلام بہت قلیل تھا اور آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے فتنہ میں ڈالا جاتا تھا یعنی یا تو اُسے قتل کیا جاتا تھا یا عذاب دیا جاتا تھا.یہاں تک کہ اسلام پھیل گیا پھر کسی کو فتنہ میں نہیں ڈالا جاتا تھا.اس سے صاف معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک فتنہ نہ رہنے سے یہ مراد ہےکہ لوگ دینی معاملات میں جبرواکراہ سے کام نہ لیں اور محض دین قبول کرنے کی وجہ سے نہ کسی کو قتل کریں.ا ور نہ کسی قسم کااورعذاب دیں.اگر یہ معنے نہ ہوتے تو فَاِنِ انْتَھَوْا کیوں آتا؟ کیونکہ یہ تو لوگوں کے بتائے ہوئے معنوں کے خلاف پڑ تاہے اور ہمارے معنوں کے مطابق ہے.وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ کے الفاظ نے بھی مذکورہ بالا حصہ کی تشریح کر دی اور بتا دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دین کا اختیار کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو جائے اور اس کے متعلق کسی اور کا ڈر نہ ہو.گویا دین کے اختیار کرنے کے بارہ میں ہرشخص کو کامل آزادی حاصل ہو جائے اور اگر لوگ مسلمان ہونا چاہیں تو وہ بغیر کسی خوف کے ہو سکیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں جبر کی تعلیم نہیں دی گئی.اگر جبر کی تعلیم ہوتی اور اس وقت تک جنگ جاری رکھنا ضروری ہوتا جب تک تمام لوگ مسلمان نہ ہو جائیں تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مشرکوں سے صلح کے معاہدات نہ کرتے.پس یہ کہنا کہ اس آیت کے معنے یہ ہیں کہ مشرکوں سے اس وقت تک لڑائی جاری رکھو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور کفر اور شرک مٹ نہ جائے بالکل غلط ہے.اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ١ؕ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینہ کے بدلہ میں ہے.اور سب (ہی) عزت والی چیزوں (کی ہتک) کا بدلہ لیا فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى جاتا ہے.اس لئے جو شخص تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر (اس کی) زیادتی کا جس قدر کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہو عَلَيْكُمْ١۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ۰۰۱۹۵ بدلہ لے لو.اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ یقیناً متقیوں کے ساتھ (ہوتا )ہے.حل لغات.اَلْحَرَامُ کے معنے ہیں اَلْمَمْنُوْعُ مِنْہُ جس چیز سے روکا گیا ہو.(مفردات)
Page 243
اپنی ذات میں کام ہیں.ایک شخص جس کا دل دنیا بھر کی بدخواہی کے خیالات سے بھرا ہوا ہے رات اور دن لوگوں پر حسد کرتا ہے.ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ بد عمل نہیں.کسی نہ کسی وجہ سے اُسے بد عمل اپنے ہاتھوں یا پیروں سے کرنے کی توفیق نہیں ملی ورنہ بد عمل تو وہ ضرور ہے.حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک عمل صالح کی صحیح تشریح خدا اور اُس کے رسول کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی.پس عملِ صالح کا پتہ بغیر ایمان کے لگ ہی نہیں سکتا.یہ مطلب نہیں کہ عملِ صالح کی کوئی جُز بھی ایسی نہیں جو بغیر ایمان کے حاصل نہ ہو سکے.سینکڑوں اجزاء عملِ صالح کے ایسے ہوں گے جن کو بغیر ایمان کے حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ ہمیں یُوں کہنا چاہیے کہ بغیر ایمان کے اُن کو حاصل کیا جاتا ہے.مگر سوال تو مکمّل تشریح کا ہے مکمل تشریح بغیر ایمان کے حاصل نہیں ہوتی.دوسرےیہ کہ قرآن کریم عملِ صالح کے دو نتائج بیان فرماتا ہے.ایک نتیجہ تو یہ بیان فرماتا ہے کہ اچھے کام کے اچھے نتائج اِس دنیا میں ملتے ہیں اور بُرے کام کے بُرے نتائج اِس دنیا میں ملتے ہیں.جھوٹ بولنے والا بدنام ہو جاتا ہے.سچ بولنے والا نیک نام ہو جاتا ہے.لوگ جھوٹے پر اعتبار نہیں کرتے سچے پر اعتبار کرتے ہیں.بددیانت کو لوگ قرض نہیں دیتے ، دیانتدار کو صرف قرض ہی نہیں دیتے بلکہ اُس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں جن سے وہ فائدہ اُٹھاتا ہے.محنتی آدمی کو زیادہ آسانی سے نوکریاں مل جاتی ہیں، کام مل جاتے ہیں اچھی تنخواہیں مل جاتی ہیں.غرض بہت سے نیک اعمال کے بدلے اِسی دنیا میں مل رہے ہیں.مگر اس آیت میں اِس دنیا کے بدلوں کا ذکر نہیں اِس آیت میں تو جنت ملنے کا ذکر ہے جو کام انسان نے اپنی مرضی سے کئے اور اُن سے فائدہ اٹھا لیا.اُن کے بدلہ میں جنّت کیوں ملے.لازمی بات ہے کہ جنّت ملنے کے لئے کوئی ایسا فعل بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے جس فعل سے اُس نے خدا کی بات مانی ہے اور وہ ایمان ہے.اِسی وجہ سے جب کبھی رسول کریم صلے اﷲ علیہ وسلم جنّت کا ذکر فرماتے تھے یہ ضرور فرماتے کہ جو شخص نیک عمل کرے اِیْمَانًا و اِحْتِسَابًا ایمان اور خدا سے نیک بدلہ کی اُمید کرتے ہوئے، تو اُس کو جنّت مل جائے گی.اِس کے یہی معنے ہیں کہ عمل کا دنیوی نتیجہ تو یہیںانسان کو حاصل ہو جاتا ہے اگلے جہان میں بدلہ ملنے کے لئے کوئی زائد عمل ہونا چاہیے اور وہ عمل ایمان ہے.ایک شخص سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی وجہ سے سوسائٹی میں اُس کی قدر ہوتی ہے کئی ایسے کاموں کے حاصل کرنے میں اُسے سہولت حاصل ہوتی ہے جن میں سچ کو قیمت دی جاتی ہے یہ شخص اپنے کام کا پھل کھا لیتا ہے اور نتیجہ پا لیتا ہے لیکن اگر ایسا شخص سچ بولتے وقت یہ بھی مدِّنظر رکھ لیتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے کہا ہے کہ سچ بول.میں اپنے خدا کی خاطر سچ بولتا ہوں تو ایسا شخص ایک تو وہ نیک کام کر رہا ہے دوسرے خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے.نیک کام کرنے کا
Page 244
وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ).وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى اور اللہ کے راستے میں (مال و جان) خرچ کرو.اور اپنے ہاتھوں ہی (اپنے آپ )کو ہلاکت میں مت ڈالو التَّهْلُكَةِ١ۛۖۚ وَ اَحْسِنُوْا١ۛۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۰۰۱۹۶ اور احسان سے کام لو اللہ (تعالیٰ )احسان کرنے والوں سے یقیناً محبت کرتا ہے.تفسیر.اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے.انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاں کوئی تکلیف پیش آتی ہے وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے ہم اس میں کس طرح حصہ لے سکتے ہیں.حالانکہ اس کے ہرگزیہ معنے نہیں کہ جہاں موت کا ڈر ہو وہاں سے مسلمان کو بھاگ جانا چاہیے اور اسے بزدلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ جب دشمن سے لڑائیاں ہو رہی ہوں تو اس وقت اپنے مالوں کو خوب خرچ کرو.اگر تم اپنے اموال کو روک لو گے تو اپنے ہاتھوں اپنی موت کا سامان پیدا کرو گے.چنانچہ احادیث میں حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے مروی ہے کہ انہوںنے اس وقت جب کہ وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے کہا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارہ میں نازل ہوئی تھی اور پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے توہم خدا تعالیٰ کے رستہ میں اپنے اموال خوب خرچ کیا کرتے تھے.لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنے دین کو تقویت اور عزّت دی اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا تو قُلْنَا ھَلُمَّ نُقِیْمُ فِیْ اَ مْوَالِنَا وَنُصْلِحُھَا (ابوداؤد کتاب الجہادباب فی قولہ لا تلقوا بایدیکم الی التھلکۃ) ہم نے کہا کہ اگر اب ہم اپنے مالوں کی حفاظت کریں اور اسے جمع کریں تو یہ اچھا ہو گا.اس وقت یہ آیت اُتری کہ اللہ تعالیٰ کے رستہ میں اپنے اموال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو.کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو.پس اپنے مالوں کو جمع نہ کرو.بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے رستہ میں خوب خرچ کرو.ورنہ تمہاری جانیں ضائع چلی جائیں گی.دشمن تم پر چڑھ آئیں گے اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم ہلاک ہو جائو گے.وَاَحْسِنُوْا اور اپنے فرائض کو عمدگی سے ادا کرو یا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو اپنے نادار اور غریب بھائیوں کے اخراجات بھی برداشت کرو اور نیکی کی نئی سے نئی راہیں تلاش کرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی
Page 245
کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے.پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غرباء کی امداد کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ تم زکوٰۃ اور عُشر وغیرہ مقررہ ٹیکس بھی دو مگر اس کے علاوہ ہم تم سے بعض طوعی ٹیکس بھی مانگتے ہیں.چنانچہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.ہمیشہ غرباء کی امداد کےلئے روپیہ دیتے رہو.وَ لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو.یعنی اے مالدارو! اگر تم اپنے زائد مال خوشی سے دے دو گے تو وہ تو زائد ہی ہیں تم کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچے گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جائو گے.یہ الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے زارِروس کے ساتھ ہونے والے واقعات کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے.اور فرمایا ہے کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو جو کچھ زارِ روس اور روسی امراء یا فرانس کے امراء کا حال ہوا وہی تمہارا ہو گا.آخر عوام ایک دن تنگ آکر لوٹ مار پر اُتر آئیں گے.اور شاہ پوری محاورہ کے مطابق دُعائے خیر پڑھ دیں گے.حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محاورہ کی تشریح یہ بیان فرمایاکرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کچھ مدت پہلے زمیندار بنیئے سے قرض لیتے جاتے تھے اور بنیا بھی دیتا چلاجاتا تھا کچھ عرصہ تک تو انہیں اس کا احساس نہ ہوتا.مگر جب سب علاقہ اس بنیئے کا مقروض ہو جاتا اور زمینداروں کی سب آمد اس کے قبضہ میں چلی جاتی تو یہ دیکھ کر اس علاقے کا کوئی بڑا زمیندار تمام چودھریوں کو اکٹھا کرتا اور کہتا کہ بتائو اس بنیئے کا قرض کتنا ہے.وہ بتاتے کہ اتنا قرض ہے اس پر وہ دریافت کرتا کہ اچھا پھر اس قرضے کے اترنے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں.وہ جواب دیتے کہ ہمیں تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا.اس پر وہ کہتا کہ اچھا تو پھر ’’دُعائے خیر پڑھ دو‘‘.چنانچہ وہ سب دُعائے خیر پڑھ دیتے.اور اس کے بعد ہتھیار لے کر بنیئے کے مکان کی طرف چل پڑتے اور اُسے قتل کر دیتے اور اس کے بہی کھاتے سب جلا دیتے.اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسی ہی حالت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس زائد مال ہو تو اُسے خدا تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کر دیا کرو.اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو.یعنی بے شک کمائو تو خوشی سے مگر اس دولت کو اپنے گھر میں جمع نہ رکھا کرو.ورنہ کسی دن لوگ تمہارے خلاف اُٹھ کھڑے ہوںگے اور تم ہلاک ہو جائو گے.پھر فرماتا ہے وَاَحْسِنُوْا.بلکہ اس سے بڑھ کر ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم نیکی کرو اور وہ اس طرح کہ تم خود اپنی ضرورتوں کو کم کر کے اور مال بچا کر خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا کرو.مگر یاد رکھو کہ یہ عمل تم لوگوں سے ڈر کر نہ کرو بلکہ خوشی سے کرو.اگر تم ڈر کر کرو گے تو غریبوں کی مدد توہو جائے گی مگر خدا تعالیٰ خوش نہیں ہو گا.لیکن اگر خوشی سے یہ
Page 246
قربانی کرو گے تو غریب بھی خوش ہوںگے.تم بھی ہلاکت سے بچ جائو گے اور خدا تعالیٰ بھی تم پر خوش ہو گا.پھر فرماتا ہے اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ اگر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ پھر ہماری کمائی کا صلہ ہم کو کیا ملا.تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا صلہ مال سے زیادہ ملے گا.اور وہ تمہارے پیدا کرنے والے خدا کی محبت ہے.تمہاری دنیا کے ساتھ تمہاری عاقبت بھی درست ہو جائےگی.یہ معنے تو سیاقِ کلام کے لحاظ سے ہیں لیکن اس کے ایک معنے صرف اس ٹکڑہ آیت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ہیں کہ عبادات میں یا کھانے پینے میں یا محنت و مشقت میں یا صفائی و طہارت میں کبھی کوئی ایسی راہ اختیار نہ کرو.جس کا نتیجہ تمہاری صحت یا تمہاری جان یا تمہاری عقل یا تمہارے اخلاق کے حق میں بُرا نکلے.تَھْلُکَۃ کا لفظ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس کے معنے کسی ایسے فعل کے ہوتے ہیں جس کا انجام ہلاکت ہو اور نتیجہ بُرا نکلے.پس اس لفظ کے استعمال کرنے سے قرآن کریم نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ اسلام دین یا عزّت یا تمدن کی حفاظت کے لئے انسان کو اپنی جان خطرہ میں ڈالنے سے نہیںر وکتا بلکہ ایسے کاموں سے روکتا ہے جن کا کوئی نیک نتیجہ برآمد ہونے کی امید نہ ہو.اور جن میں انسان کی جان یا کسی اور مفید شے کے بلاوجہ برباد ہونےکا خطرہ ہو.وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ١ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اور حج اور عمرہ کو اللہ (کی رضا) کے لئے پورا کرو.پھر اگر تم (کسی سبب سےحج اور عمرہ سے) روکے جاؤ اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ١ۚ وَ لَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى تو جو قربانی میسّر آئے (ذبح کرو) اور جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر (نہ) پہنچ جائے اپنے سر نہ مونڈو.يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ١ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اور جو کوئی تم میںسے بیمار ہو یا اپنے سر (کی بیماری کی وجہ )سے اسے تکلیف (پہنچ رہی )ہو اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ (اور وہ سر مونڈوادے) اس پر (اس وجہ سے) روزوں یا صدقہ یا قربانی کی قسم سے کچھ فدیہ (واجب) ہوگا.
Page 247
نُسُكٍ١ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ١ٙ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ پھر جب تم امن میں آجاؤ.تو اس وقت جو شخص عمرہ کا فائدہ (ایسے) حج کے ساتھ (ملا کر)اٹھائے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ١ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ تو جو قربانی بھی آسانی سے مل سکے (کر دے) اور جو(کسی قربانی کی بھی توفیق) نہ پائے (اس پر)تین دن کے اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ١ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ روزے تو حج (کے دنوں ) میں واجب ہو ں گے اور سات (روزے) جب (اے مسلمانو!) تم (اپنے گھروں کو) كَامِلَةٌ١ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ واپس لوٹ آؤ.یہ پورے دس ہوئے.یہ حکم اس شخص کے لئے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس رہنے الْحَرَامِ١ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِؒ۰۰۱۹۷ والے نہ ہوں.اور تم اللہ کا تقویٰ اختیارکرو اور سمجھ لو کہ اللہ کی سزا یقیناً سخت (ہوتی) ہے.تفسیر.یہاں سے حج اور عمرہ کے احکام کا آغازہوتا ہے.حج اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رُکن ہے.اور ہر شخص جو بیت اللہ کا حج کرنا چاہے اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ میقات پر پہنچنے کے بعد احرام باندھ لے.میقات ان مقامات کو کہتے ہیں جہاں پہنچنے پر اسلامی ہدایات کے مطابق حاجیوں کو احرام باندھنا پڑتا ہے.مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذوالحلیفہ.شام کی طرف سے آنے والوں کے لئے جُحفہ.عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے ذات عرق.نجد کی طرف سے آنےوالوں کے لئے قرن المنازل اور یمن کی طرف سے آنے والوں کے لئے یلملم میقات مقرر ہیں.پاکستان سے جانے والوں کےلئے یلملم ہی میقات ہے اور حاجیوں کو جہاز میں ہی احرام باندھنا پڑتا ہے.جو لوگ ان میقات کے اندر رہتے ہوں انہیں احرام کے لئے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی.وہ اپنی اپنی جگہوں سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں.احرام کا طریق یہ ہے کہ انسان حجامت بنوا کر غسل کرے.خوشبو لگائے.اور اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر تہہ بند کے طور پر کمر سے باندھ
Page 248
لے اور دوسری چادر جسم کے اوپر اوڑھ لے.سر کو ننگا رکھے اور دور کعت نفل پڑھے اور اس کے بعد اپنے اوقات کا اکثر حصہ تکبیر و تلبیہ اور تسبیح و تحمید میں بسر کرے اور بار بار لَبَّیْکَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّمَعْۃَ لَکَ وَالْمُلْکَ لَاشَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ کہتا رہے.ہر نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہنا چاہیے.محرم کے لئے سِلے ہوئے کپڑے یعنی قمیص شلوار پاجامہ یا کوٹ وغیرہ پہننا، سر کو ڈھانپنا، جرابیں پہننا، خوشبو لگانا ،خوشبودار رنگوں سے رنگے کپڑے پہننا، سرمنڈوانا، ناخن اتارنا، جوئیں نکالنا یا ان کو مارنا، جنگل کے کسی جانور کا شکار کرنا، شکار کے جانور کو ذبح کرنا، کسی کو شکار کےلئے کہنا یا کسی شکاری کی مدد کرنا، شہوانی تعلقات قائم کرنا یا شہوانی گفتگو کرنا،فحش کلامی کرنا یا فحش اشعار پڑھنا، فسق و فجور اور لڑائی جھگڑے میں حصہ لینا، یہ سب امور ناجائز ہوتے ہیں.البتہ محرم غسل کر سکتا ہے کپڑے دھو سکتا ہے اور دریائی جانور کا شکار بھی کر سکتا ہے.محرم عورت کے لئے بھی ان ہدایات کی پابندی ضروری ہے البتہ اُسے بے سلے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں.اُسے اپنا معمولی لباس یعنی قمیص پاجامہ اور دوپٹہ ہی رکھنا چاہیے البتہ وہ برقعہ نہیں اوڑھ سکتی.جب حاجی حدودِ حرم میں داخل ہو (یعنی مکہ معظمہ اور اس کے ارد گرد کے علاقہ میں جو حرم کہلاتا ہے) تو وہ آدابِ حرم کو ملحوظ رکھے.اور جب بیت اللہ پر پہلی مرتبہ نظر پڑے تو اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً دُعا کےلئے اپنے ہاتھ اُٹھا دے کیونکہ وہ قبولیت دُعا کا خاص وقت ہوتاہے اس کے بعد جب بیت اللہ کے پاس پہنچے تو حجرا سود سے خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے.طواف کرتے ہوئے اگر ممکن ہو تو ہر دفعہ حجرا سود کو بوسہ دینا چاہیے اور اگر ممکن نہ ہو تو صرف ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر دینابھی کافی ہے.طواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نفل پڑھے اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ چکر لگائے.صفا سے مروہ تک ایک چکر شمار ہو گا اور مروہ سے صفا تک دوسرا پھر مکہ معظمہ میں ٹھہر کر ایام حج کا انتظار کر ےجب ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ ہو تو وہ مکہ سے منیٰ چلا جائے اوروہاں پانچوں نمازیں پڑھے پھروہاں سے دوسری صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد عرفات کی طرف ایسے وقت میں چلے کہ وہاں بعد زوال داخل ہو اور ظہر و عصر کی نمازیں وہاں جمع کر کے ادا کرے اور سورج کے ڈوبتے تک عرفات میں ہی رہے اور دعائوں اور عبادت میں اپنا وقت گذارے اس کے بعد مزدلفہ مقام میں آئے.جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھے او روہاں رات بھر عبادت اور دعائوں میں بسر کرے.فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مشعر الحرام پر جا کر دُعا کرے.اور وہاں سے سورج نکلنے سے پہلے ہی روانہ ہو کر منیٰ پہنچے اور وہاں جا کر جمرۃ العقبہ پر سات کنکریاں مارے اور ہر دفعہ کنکر پھینکنے کے ساتھ ساتھ تکبیر کہے.مگر یہ کام سورج نکلنے کے بعد
Page 249
کرے.یہاں سے فارغ ہو کر قربانی کرے.سر منڈوائے اور پھر اسی دن شام تک یا اگلے دن مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرے.افضل یہ ہے کہ اسی دن شام تک جا کر کعبہ کا طواف کر آئے.پھر دوسرے دن منیٰ میں واپس آجائے.اور بعد زوال جمرۃ الدنیا.جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ العقبہ پر سات سات پتھر مارے.اسی طرح تیسرے دن اور پھر چوتھے دن بھی جو ایام تشریق کہلاتے ہیں یعنی گیارھویں بارھویں اور تیرھویں ذوالحج کو تیرھویں تاریخ کو منیٰ سے واپس آجائے اور بیت اللہ کا طواف الوداع کرے.جو شخص یہ تمام مناسک بجا لائے وہ فریضہ حج ادا کر لیتا ہے.اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر خرو ہو جاتا ہے.عمر ہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر رہنے والا ہو تو وہ حرم سے اور اگر باہر کا ہو تو میقات سے احرام باندھے خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کرے.صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے اور پھر حلق یا قصر کر دے.اور اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی بھی کر دے.لیکن عمرہ میں قربانی لازمی نہیںہوتی.حج اور عمرہ میں یہ فرق ہے کہ عمرہ کے لئے کسی خاص وقت یا مہینہ کی قید نہیں بلکہ وہ سال کے ہر حصہ میں ہو سکتا ہے جبکہ حج صرف شوال.ذوالقعدہ اور ذوالحج میں ہی کیا جا سکتا ہے.ترمذی میں حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کے متعلق پوچھا کہ اَوَاجِبَۃٌ ؟ کیا عمرہ واجب ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا لَا، وَ اَنْ تَعْتَمِرُوْ ا خَیْرٌ لَّکُمْ عمرہ واجب تو نہیں لیکن اگر تم عمرہ کرو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے.(ترمذی کتاب الحج باب ما جاء فی العمرۃ أواجبۃ ھی او لا) فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ.اس میں بتایا کہ اگر حج یا عمرہ کرنے والا کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا جنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے راستہ میں ہی روک دیا جائے اور وہ مکہ مکرمہ جا کر حج یا عمرہ نہ کر سکے تو پھر جو قربانی بھی میسّر آئے اُسے دے دینی چاہیے اور اس وقت تک احرام نہیں کھولنا چاہیے جب تک کہ قربانی محلّہٗ نہ پہنچ جائے.یعنی اس جگہ پر جہاں قربانی نے ذبح ہونا ہے.ابن القاسم کا قول ہے کہ اگر قربانی ساتھ ہو تب قربانی دے ورنہ نہیں اور جمہور کا قول ہے کہ جس جگہ روکا جائے وہیں قربانی کر دے اور سر منڈوا ڈالے جو سب سے آخر ی عمل ہے اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے (بحر محیط زیر آیت ھذا) امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک بھی مَحِلَّہٗ سے مراد وہی جگہ ہے جہاں حاجی کو روک دیا گیا ہو.لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرم ہے.میرے نزدیک یہ جھگڑا فضول ہے کیونکہ اگر تو جنگ ہو اور دشمن نے اُسے روکا ہو تو وہ اس کی قربانی کو آگے کیسے جانے دےگا.ایسی صورت میں وہ جہاں روکا جائے وہیں قربانی کر کے حلق کر دے لیکن اگر بیماری کے سبب سے
Page 250
حاجی کو روکا گیا ہو اور وہ قربانی آگے بھجوا سکتا ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ قربانی کے حرم پہنچنے تک سر نہ منڈوائے اور کوشش کرے کہ وہ حرم کے اندر ہی ذبح ہو.اس کے بعد حلق کر دے.ضمنی طور پر اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت سے جبراً روک دیا جائےگا لیکن اس کے بعداللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو کفار پر فتح عطا فرمائےگا اور وہ امن سے حج بیت اللہ کر سکیں گے.چنانچہ صلح حُدیبیہ میں ایسا ہی ہوا.باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم صرف طواف کی نیت سے تشریف لے گئے تھے.قریش نے اطلاع ملنے پر چیتوں کی کھالیں پہن لیں اور اپنی بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے لیا اور قسمیں کھائیں کہ وہ مر جائیں گے مگر آپؐ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیںگے.آخر یہ معاہد ہ طے پایا کہ اس سال مسلمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں اور اگلے سال آکر طواف کر لیں.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور تمام صحابہؓ واپس چلے گئے مگر ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا اور مسلمان آزادی کے ساتھ آنے جانے لگے.فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖۤ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ.فرماتا ہے.اگر کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو جس کی وجہ سے اُسے سر منڈوانا پڑے.جیسے اس کے سر میں جُوئیں پڑ جائیں یا پھوڑے نکل آئیں تو وہ سر منڈوا سکتا ہے.مگر اس صورت میں اسے صیام یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا پڑے گا.قرآن کریم میں فدیہ کی تینوں اقسام کو غیر معین رکھا ہے.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ایک ارشاد سے اس کی تعیین ہو جاتی ہے.حدیثوں میں آتا ہے کہ کعب بن عجرہؓ ایک صحابی تھے ان کے سر میں جُوئیں پڑ گئیں.اور ان کی اتنی کثرت ہو گئی کہ جو ئیں ان کے منہ پر گرتی تھیں وہ کہتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا.اے کعب! تجھے ان جوئوں کی وجہ سے بہت تکلیف ہے تو سر منڈوا دے اور صُمْ ثَلَاثَۃَ اَیَّامٍ اَوْ اَطْعِمْ سِتَّۃَ مَسَاکِیْنَ اَوْ اُنْسُکْ بِشَاۃٍ.تو فدیہ کے طور پر تین دن کے روزے رکھ لے چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری کی قربانی دے دے(مؤطا امام مالک کتاب الحج باب فدیۃ من حلق قبل ان ینحر).میرے نزدیک اس آیت میں جو فدیہ کی ترتیب ہے وہ امارت اور غربت کے لحاظ سے ہے.یعنی اگر کوئی شخص غریب ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھ لے.اگر متوسط درجہ کا ہو تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور اگر مالدار ہوتو قربانی دے دے.بہر حال قربانی مقدم ہے اور اس کے بعد صدقہ ہے اور اس کے بعد روزے ہیں اور یہ ترتیب درجہ کی بلندی کے لحاظ سے ہے.یعنی ادنی ٰ فدیہ یہ ہے کہ تین دن کے روزے رکھے اس سے اعلیٰ فدیہ یہ ہے کہ
Page 251
چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے.اور اس سے اعلیٰ فدیہ یہ ہے کہ ایک قربانی دے دے.اور یہ حکم محصرکے لئے نہیں بلکہ محصر اور غیر محصر دونوں کے لئے ہے.محصر کا حکم مَحِلَّہُ تک ختم ہو گیا ہے.فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَۃِ اِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْھَدْیِ.فرماتا ہے جب جنگ ختم ہو جائے یا دوسری روکاوٹیں دور ہو جائیں تو اس کے بعد جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اُٹھائے اور قرِان یا تمتع کر ےتو جو قربانی بھی آسانی سے میسّر آسکے کر دے.حج اور عمرہ کے الگ الگ ادا کرنے کا ذکر تو پہلے آچکا ہے.اب دونوں اکٹھے ادا کرنے کا ذکر فرماتا ہے.میرے نزدیک اس جگہ تمتع سے اصطلاحی تمتع مراد نہیں بلکہ قران اور تمتع دونوں مراد ہیں.اور تمتع کے معنے لغوی ہیں فائدہ اٹھائے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ چار رنگ میں جاتے ہیں.اوّل صرف حج کے لئے.دوم صرف عمرہ کے لئے.سوم تمتع کے لئے.چہارم قران کے لئے.تمتع اور قران دونوں میں قربانی واجب ہے.لیکن حج اور عمرہ میں نہیں.اسی طرح عمرہ تو سال کےدوران میں ہر وقت ہو سکتا ہے اور حج سال میں صرف ایک ہی دفعہ مقررہ ایام میں ہو سکتاہے.پس اگر کوئی شخص صرف عمرہ کے لئے جائے یا صرف حج کے لئے جائے اور عمرہ کی نیت نہ ہو تو یہ امر اس کے حالات پر منحصر ہے کہ وہ قربانی کرے یا نہ کرے.لیکن قِران جس میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہوتی ہےاس میں قربانی واجب ہوتی ہے.قِران یہ ہے کہ اشہر الحج میں انسان میقات سے احرام باندھ کر حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کرے اور مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کے احکام بجا لائے اور جب تک حج سے فارغ نہ ہو احرام نہ کھولے.بعض کے نزدیک اس پر ایک سعی اور ایک طواف ہے اور بعض کے نزدیک دو طواف اور دو سعی.اور جب لوٹنا چاہے تو طواف وداع کرے.اس میں عمرہ کے بعد اس وقت تک احرام نہیں کھولا جاتا جب تک کہ حج نہ ہو جائے حج کرنے کے بعد احرام کھولا جاتاہے.لیکن اگر تمتع کی نیت سے جائے تو اشہر الحج میں عمرہ کی نیت کر کے میقات سے احرام باندھے اور مکہ میں داخل ہو پہلے طواف کرے پھر سعی کرے.پھر حلق یا قصر کرے اور جب عمرہ ہو چکے تو احرام کھول دے اور ذوالحج کی آٹھویں تاریخ کو حج کے لئے پھر نیا احرام باندھے اور حج کرے.اس میں بھی قربانی واجب ہے.اس میں عمرہ کرنےکے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور حج کے لئے نئے سرے سے احرام باندھا جاتا ہے.غرض قِران اور تمتع دونوں میں قربانی واجب ہے.لیکن اکیلے عمرہ یا حج میں واجب نہیں بلکہ مستحبّ ہے.اور اگر ان میں سے کسی کی نیت کر کے جائے اور کسی وجہ سے روکا جائے تو اس پر قربانی واجب ہو گی اور جب تک قربانی ذبح نہ ہو اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ سر نہ منڈوائے.ہاں اگر قربانی مکہ مکرمہ میں بھیج سکتا ہو تو بھیج دے اور پھر جب
Page 252
تک قربانی وہاں پہنچ نہ جائے اس وقت تک سر نہ منڈائے.غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمتع اور قِران کی خصوصیات جو خالی حج اور خالی عمرہ کے مقابلہ میں ہیں بیان فرمائی ہیں.اور فَاِذَا اَمِنْتُمْ کے الفاظ اس لئے بڑھائے ہیں کہ اس حکم کو پہلے حکم کا حصہ نہ سمجھ لیا جائے.اس حکم کو احصار کے ذکر کے بعد اس لئے بیان کیا کہ اس صورت میں بلا احصار قربانی ہونی چاہیے اور حج اور عمرہ میں احصار سے قربانی ہوتی ہے ورنہ نہیں.اس لئے اس کو احصار کے ذکر کے بعد بیان کیا.اس جگہ تمتع اور قِران کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ ان میں قربانی ضروری ہو گی خواہ احصار نہ ہی ہوا ہو.اور جسے اس کی توفیق نہ ہو وہ جیسا کہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے تین دن کے روزے مکہ میں اور سات دن کے روزے واپس آکر رکھے.فرماتا ہے فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ.(۱) بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تین دن کے روزے ذوالحج کی ساتویں.آٹھویں اور نویں تاریخ کو رکھے جائیں (۲) حضرت امام ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ اگر وہ ان ایام میں روزے نہیںرکھےگا تو اس پر قربانی بھی واجب ہو گی (۳) بعض کہتے ہیں کہ یہ روزے چونکہ قربانی کے بدلہ میں ہیں اس لئے حج کے بعدرکھنے چاہئیں (۴) بعض کہتے ہیں کہ یہ روزے واپسی سے پہلے مکہ میں ہی رکھنے چاہئیں (۵) بعض نے احرام عمرہ اور احرام حج کے درمیانی عرصہ میں روزے رکھنے کو کہا ہے.(بحر محیط زیر آیت ھذا ).میرے نزدیک یہ روزے ایام تشریق یعنی گیارھویں بارھویں اور تیرھویں ذوالحجہ کو رکھنے چاہئیں اور فِی الْحَجِّ سے مراد اس جگہ فِیْ اَیَّامِ الْحَجِّہے.باقی سات روزے گھر پر بھی رکھے جا سکتے ہیں.اس جگہ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ کا فقرہ اس لئے زائد کیا گیا ہے کہ وَسَبْعَۃٍ کی جگہ اَوْ نہ سمجھ لیا جائے اور غلطی سے یہ معنے نہ کر لئے جائیں کہ وہاں رکھے تو تین رکھے اور گھر رکھے تو سات رکھے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے آخر میں تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فرما کر بتا دیا کہ صرف تین یا سات روزے رکھنا مراد نہیں بلکہ پورے دس روزے رکھنے مراد ہیں یا یہ الفاظ تاکید کے لئے استعمال کئے گئے ہیں.اور تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ کے یہ معنے ہیں کہ یہ روزے ثواب یا قربانی کے قائم مقام ہونے کے لحاظ سے کامل فدیہ ہیں.ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرماتا ہے یہ حکم یعنی تمتّع کا صرف باہر کے لوگوں کے لئے ہے کیونکہ ان کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے مکہ والے تو ہر وقت عمرہ کر سکتے ہیں ان کے لئے تمتّع یا قِران نہیں ہے.اس آیت کے بارہ میں مفسّرین میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے (۱) بعض کہتے ہیں کہ قربانی نہ ملنے کی
Page 253
صورت میں روزوں کا حکم صرف آفاقیوں کے لئے ہے مکہ والوں کے لئے نہیں کیونکہ وہ تو اپنے شہر میں ہی قربانی مہیا کر سکتے ہیں.یہ امام شافعی کا مذہب ہے.(۲) بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت روزوں کے متعلق ہے.یعنی روزوں کا حکم اہل مکہ کے لئے نہیں بلکہ صرف باہر والوں کے لئے ہے.گویا انہوں نے صیام کو ذٰلِکَ کے ماتحت رکھا ہے مگر میرے نزدیک یہ دونوں درست نہیں کیونکہ اس صورت میں مکہ والوں کو سہولت رہتی ہے (۳) امام ابو حنیفہ ؒ کہتے ہیں کہ اس سے تمتّع اور قِران والے احکام مراد ہیںجن کا ذکر فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ میں آچکا ہے اور ا س کے معنے یہ ہیں کہ تمتّع اور قِران اہل مکہ کے لئے جائز نہیں(بحر محیط زیر آیت ھذا).میرے نزدیک امام ابو حنیفہ ؒ کے معنے زیادہ درست ہیں اور عقل بھی انہی کی تائید کر تی ہے.کیونکہ مکہ والے تو ہر وقت عمرہ کر سکتے ہیں.اس کے بعد حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں بھی اختلاف ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں (۱) حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے تمام اہل حرم مرا د ہیں (۲) عطاء کہتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہر جہت سے مواقیت کے اندر رہتے ہیں (۳)زہری کہتے ہیں کہ ایک یا دو دن کے سفر تک رہنے والے مراد ہیں (۴)بعض کہتے ہیں کہ اس سے صرف اہل مکہ مراد ہیں اور یہی معنے زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتے ہیں.آخر میں فرمایا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو.یعنی حج کی عبادت محض اس غرض کے لئے ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ پیداہو.اور تم ماسوی اللہ سے نظر ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی ڈھال بنا لو.اگر حج بیت اللہ یا عمرہ سے کسی کو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا کوئی مخفی کبر اس کے سامنے آگیا ہے اسے چاہیے کہ خلوت کے کسی گوشہ میں اپنے خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ دے اور جس قدر خلوص بھی اس کے دل میں باقی رہ گیا ہو اس کی مدد سے گریہ و زاری کرے یا کم سے کم گِریہ وزاری کی شکل بنائے اور خدا تعالیٰ کے حضور جھک کر کہے کہ اے میرے خدا! لوگوں نے بیج بوئے اور ان کے پھل تیار ہونے لگے وہ خوش ہیں کہ ان کے اور ان کی نسلوں کے فائدہ کے لئے روحانی باغ تیار ہو رہے ہیں.پر اے میرے رب! میں دیکھتا ہوں کہ جو بیج میں نے لگایا تھا اس میں سے تو کوئی روئیدگی بھی پیدا نہیں ہوئی.نہ معلوم میرے کِبر کاکوئی پرندہ اُسے کھا گیا یا میری وحشت کا کوئی درندہ اسے پاؤں کے نیچے مسل گیا یا میری مخفی شامت اعمال ایک پتھر بن کر اس پر بیٹھ گئی.اور اس میں سے کوئی روئیدگی نکلنے نہ دی.اے خدا! اب میں کیا کروں کہ جب میرے پاس کچھ تھا میں نے بے احتیاطی سے اُسے اس طرح خرچ نہ کیا کہ نفع اٹھاتا.مگر آج تو میرا دل خالی ہے.میرے گھر میں ایمان کا کوئی دانہ نہیں کہ میں بوئوں اے خدا! میرے اس ضائع شدہ بیج کو پھر مہیّا کر دے اور میری کھوئی ہوئی متاع ایمان مجھے واپس عطا کر.اور اگر
Page 254
میرا ایمان ضائع ہو چکا ہے تو تو اپنے خزانے سے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اس دھتکارے ہوئے بندہ کوایک رحمت کا بیج عطا فرماتاکہ میں اور میری نسلیں تیری رحمتوں سے محروم نہ رہ جائیں اور ہمارا قدم ہمارے سچی اور اعلیٰ قربانی کرنےوالے بھائیوں کے مقام سے پیچھے ہٹ کر نہ پڑے بلکہ تیرے مقبول بندوں کے کندھوں کے ساتھ ساتھ ہمارے کندھے ہوں.وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِمیں اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہمیشہ خائف رہو اور اپنے تمام کاموں کی تقویٰ اللہ پر بنیاد رکھو ورنہ تمہارا پہلا ایمان بھی ضائع ہو جائےگا اور تم خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مورد بن جائو گے.اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ١ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا حج( کے مہینے سب کے)جانے بوجھے ہوئے مہینے ہیں.پس جو شخص ان میں حج (کا ارادہ )پختہ کرلے (اسے یاد رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ١ۙ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ١ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ رہے کہ)حج (کے ایام) میں نہ تو کوئی شہوت کی بات نہ کوئی نافرمانی اور نہ کسی قسم کا جھگڑا کرنا (جائز) ہوگا.اور نیکی خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ١ؔؕ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ١ٞ (کا)جو (کام ) بھی تم کر و گے اللہ (ضرور )اس (کی قدر )کو پہچان لے گا.اور زاد راہ (ساتھ) لو اور( یاد رکھو کہ) وَ اتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ۰۰۱۹۸ بہتر زاد راہ تقویٰ ہے.اور اے عقل مندو! میرا تقویٰ اختیار کرو.حل لغات.رَفَثَ مصدر ہے اور لانفی جنس کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے.رَفَثَ سے مراد ہر ایسا کلام ہے جس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جائے جسے عرف میں برا سمجھا جاتا ہو.(۲) ایسی بات جس کے اندر جماع یا اس کے متعلقات کا ذکر ہو.(۳) جب اس کے بعد اِلیٰ صلہ ہو تو اس وقت کنایہ کے طور پر اس کے معنے جماع کے لئے جاتے ہیں (مفردات) اور طبری نے کہا ہے اَلرَّفَثُ اَللَّغْوُ مِنَ الْکَلَامِ (بحرِ محیط) رفث لغو اور
Page 255
بے ہودہ گفتگو کو بھی کہتے ہیں.فُسُوْقَ فَسَقَکا مصدر ہے اور فسوق کے معنے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترک کر دینا.(۲) نافرمانی (۳) سچے راستہ سے دوسری طرف جُھک جانا.(اقرب) جِدَالَ باب مفاعلہ سے مصدر ہے اور اس کے معنے جھگڑا کرنے کے ہیں.(اقرب) زَاد جس چیز کو انسان بطور سفر خرچ اپنے ساتھ لے لے.اِتَّقُوْن امر جمع کا صیغہ ہے جو وَقٰی سے باب افتعال کے مضارع کے صیغہ سے بنا ہے.اِتَّقَا ءٌ (مصدر) جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے.یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مفعول ہو تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنا لینا.تفسیر.اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حج کے بارہ میں قرآن کریم نے کوئی نیا حکم نہیں دیا بلکہ اسی حکم کو قائم رکھا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سےچلا آرہا ہے.اس وجہ سے حج کے مہینے بھی سب لوگوں کو معلوم ہیں یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ.گو امام ابو حنیفہ ؒ اور امام شافعی ؒ کے نزدیک ذوالحج کے صرف دس دن اشہر الحج میں شامل ہیں(بحر محیط زیر آیت ھٰذا).فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَ لَا فُسُوْقَ وَ لَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ جو شخص ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر فرض کر کے چل پڑے.اُسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو پاک رکھے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جو جنسی جذبات کو برانگیختہ کرنے والی ہو.بعض لوگ کہتے ہیں کہ عشقیہ اشعار پڑھنا اس میں داخل نہیں.کیونکہ حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایام حج میں جاہلیت کے اشعار پڑھے تھے (درمنثور).یہ روایت اگرچہ قرآن کریم کے اس واضح حکم کی موجودگی میں درست تسلیم نہیں کی جا سکتی.لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا تو امتدادِ زمانہ کی وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کس غرض کے ماتحت جاہلیت کے اشعار پڑھے تھے.ممکن ہے انہوں نے دوران گفتگو میں کسی دلیل کے لئے پڑھے ہوں اور سننے والوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہو کہ وہ شوقیہ طور پر اس قسم کے اشعار پڑھ رہے ہیں.بہر حال اس قسم کا کلام خواہ وہ نظم میں ہو یا نثر میں اس سے اجتناب کرنا چاہیے.اور ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے.مگر اس ممانعت کے یہ بھی معنے نہیں کہ رفث.فسوق اور جدال دوسرے دنوں میں جائز ہے.بلکہ اس ممانعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ اگر کچھ عرصہ تک انسان اپنے نفس پر دبائو ڈال کر ایسے کام چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اُسے دوسرے دنوں میں بھی ان کو چھوڑنے کی توفیق مل جاتی ہے کیونکہ مشق ہونے کی وجہ سے اس کے
Page 256
لئے سہولت پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ بشری کمزوریوں کی وجہ سے انسان ایک لمبے وقت کے لئے کسی کام کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا.ایسی حالت میں اس کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اسے کچھ وقت کے لئے اس کام سے روک دیا جائے.جب کچھ عرصہ تک رکا رہتا ہے تو اس کی ضبط کی طاقت بڑھ جاتی ہے.اور آہستہ آہستہ وہ کلّی طور پر اس کام کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے.اسی نکتہ کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینہ میں اپنی کمزوریوں میں سے کسی ایک کمزوری پر غالب آنے کی کوشش کرے اور مہینہ بھر اس سے بچتا رہے اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اس کی مدد کرےگا اور اسے ہمیشہ کے لئے اس بدی پر غالب آنے کی توفیق عطا فرما دےگا.یہاں رفث فسوق اور جدال تین گناہوں کے چھوڑنے کا ذکر کیا گیا ہے.رفث مرد عورت کے مخصوص تعلقات کو کہتے ہیں.لیکن اس کے علاوہ بد کلامی کرنا، گالیاں دینا، گندی باتیں کرنا، قصے سُنانا، لغو اور بے ہودہ باتیں کرنا جسے پنجابی میں گپیں مارنا کہتے ہیں.یہ تمام امور بھی رفث میں ہی شامل ہیں.اور فسوق وہ گناہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں جن میں انسان اس کی اطاعت اور فرمانبرداری سے باہر نکل جاتا ہے.آخر میں جدال کا ذکر کیا ہے جو تعلقات باہمی کو توڑنے والی چیز ہے ان تین الفاظ کے ذریعہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے تین اصلاحوں کی طرف توجہ دلائی ہے.فرمایا ہے (۱) اپنی ذاتی اصلاح کرو اور اپنے دل کو ہر قسم کے گندے اور ناپاک میلانات سے پاک رکھو.(۲) اللہ تعالیٰ سے اپنا مخلصانہ تعلق رکھو (۳) انسانوں سے تعلقات محبت کو استوار رکھو.گویا یہ صرف تین بدیاں ہی نہیں جن سے روکا گیا ہے بلکہ تین قسم کی بدیاں ہیں جن سے باہر کوئی بدی نہیں رہتی.کیونکہ بدی یا تو اپنے نفس سے تعلق رکھتی ہے یا خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے.اور یا پھر مخلوق سے تعلق رکھتی ہے.اور روحانیت کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنی ذاتی اصلاح کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی سرگرم رہے.وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ.فرماتا ہے تمہیں ان باتوں کے چھوڑنے میں کئی قسم کی دقتیں پیش آئیں گی.مثلاً کسی شخص کو گالی دے دی جائے تو اس کےلئے صبر کرنا بڑامشکل ہو جاتا ہے.لیکن اگر تم خدا کے لئے ان پابندیوں کو اپنے اوپر عائد کر و گے اور نیکیوں میں حصہ لو گے تو تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے ضرور ظاہر کر دےگا.خدا تعالیٰ کی یہ سنّت ہے کہ وہ نیکی کو پوشیدہ نہیں رہنے دیتا.گو بعض صورتوں میں نیکیوں پر پردہ بھی پڑا رہتا ہے مگر آخر کار نیکی ظاہر ہو کر رہتی ہے اور دشمن بھی اس کو محسوس کئے بغیر نہیں رہتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کو ہی دیکھ لو! وہ آپ کو گالیاں دیتے تھے مگر ابو سفیان ہر قل کے سامنے آپ ؐ کا کوئی عیب بیان نہ کر سکا.صرف
Page 257
اتنا ہی کہہ سکا کہ اب ایک عہدہم میں اور اس میں ہوا ہے معلوم نہیں وہ اسے پورا کرتا ہے یا نہیں(بخاری کتاب الوحی باب کیف کان بدء الوحی).تو فرمایا کہ تم جو نیکی بھی کرو گے خدا تعالیٰ اُسے ضرور ظاہر کردے گا اور لوگوں پر تمہارے اچھے کردار اور بلند اخلاق کا گہرا اثر پڑے گا.وَ تَزَوَّدُوْا.فرمایا جب تم سفر کے لئے نکلو توہمیشہ اپنے ساتھ زادراہ لے لیا کرو.اس جگہ تَزَوَّدُوْا سے دونوں زاد مراد ہو سکتے ہیں یہ بھی کہ آمدو رفت اور کھانے پینے کے اخراجات کا انتظام کر لیا کرو.اور یہ بھی کہ نیکی اور تقویٰ کا زاد ساتھ لو.چونکہ اس سے پہلے وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَیْرٍ یَّعْلَمْہُ اللّٰہُ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور حسنات میں ترقی کرنے کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی تھی اس لئے تَزَوَّدُوْا کہہ کر بتایا کہ حج اور عمرہ کا ثواب تو بہت بڑا ہے.مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ تم زیارت کعبہ کے شوق میں خالی ہاتھ اپنے گھروں سے نکل پڑو اور لوگوں سےبھیک مانگتے ہوئے وہاں پہنچو.تمہارا کام یہ ہے کہ تم پہلے زادِ راہ کا انتظام کرو.اور جب آمد و رفت اور رہائش اور کھانے پینے وغیرہ کے تمام اخراجات کا انتظام ہو جائے تو اس کے بعد سفر کے لئے نکلو.فَاِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوٰی اور یاد رکھو کہ بہتر زادراہ ہے جس سے تم سوال اور گناہ سے بچو.افسوس ہے اس زمانہ میں مسلمانوں میں عام طور پر یہ سمجھا جاتاہے کہ اسلام اس امر کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو اسباب سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ اپنے تمام معاملات خدا تعالیٰ پر چھوڑ دینے چاہئیں.مگر یہ قطعاً غلط اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے اس لئے یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ جب تم سفر کے لئے نکلو تو ضروری سامان اور زادِ راہ سے کبھی غفلت اختیار نہ کرو.لیکن تَزَوَّدُوْا کے ایک معنے یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ تم تقویٰ کا زاد لو.اور چونکہ تقویٰ کا زاد مخفی تھا اس لئے اسے فَاِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوٰی کے الفاظ میں کھول کر بیان کر دیا اور بتایا کہ تقویٰ سب سے بہتر زاد ہے جو آخرت کے سفر میں تمہارے کام آنے والا ہے انہیں معنوں میں بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ’’وقت تھوڑا ہے اور کارے عمر ناپیدا.تیز قدم اٹھائو کہ شام نزدیک ہے جو کچھ پیش کرنا ہے وہ باربار دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ کچھ رہ جائے اور زیاں کاری کا موجب ہو یا سب گندی اور کھوٹی متاع ہو.جو شاہی دربار میں پیش کرنے کے لائق نہ ہو‘‘.(کشتی نوح روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۶) چونکہ اس سے پہلے حج کا ذکر آچکا ہے اس لئے فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى.فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اب حج سے تمہاری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے تمہیں تقویٰ کا پہلے سے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے
Page 258
جیسے صاف کپڑوں والا چھوٹے چھوٹے داغ اور دھبے سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرتا ہے.پھر فرماتا ہے وَ اتَّقُوْنِ يٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ.اے عقلمندو! اگر تم اپنے بچائو کا سامان کرنا چاہتے ہوتو میری طرف جھکو.اور صرف مجھے ہی اپنی حفاظت کا ذریعہ بنائو.باقی تمام ذرائع اس کے مقابلہ میں بالکل ہیچ ہیں.لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ١ؕ فَاِذَاۤ تمہارے لئے (یہ) کوئی گناہ(کی بات) نہیں کہ (حج کے ایام میں ) اپنے رب سے کوئی(اور) فضل بھی مانگ لو.اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ١۪ پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو.اور جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے (اس وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ١ۚ وَ اِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ۰۰۱۹۹ کےمطابق )اسے یاد کرو.اور اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے.حلّ لُغات.کَمَا کے معنے ’’جس طرح‘‘ کے بھی ہوتے ہیں.اور ’’اس لئے‘‘ کے بھی چنانچہ سیبویہ کہتا ہے کَمَا اِنَّہُ لَا یَعْلَمُ تَجَاوَزَاللّٰہُ عَنْہُ کہ چونکہ وہ نہ جانتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ معاف کر دیا.(بحر محیط زیر آیت ھٰذا) اِنْ یہ اِنَّ سے مخفّفہ ہے اور اس کے معنے قریباً ’’گو‘‘ کے ہوتے ہیں.بعض کہتے ہیں کہ اِنْ نافیہ ہے یہ فرّاء کا قول ہے.کَسائی کہتا ہے کہ اِنْ کے معنے قَدْ کے بھی ہوتے ہیں اور اس جگہ اس کے معنے قَدْ کے ہی ہیں.(بحر محیط) تفسیر.فرماتا ہے تمہارے لئے یہ کوئی گناہ کی بات نہیں کہ حج کے ایام میں تم اپنے ربّ سے کوئی اور فضل بھی مانگ لو.بعض لوگ کہتے ہیں کہ فضل سے مراد اس جگہ تجارت ہے اور میرے نزدیک بھی یہ درست ہے مگر فضل سے صرف تجارت مراد لینا ایک وسیع مضمون کو محدود کر دینا ہے.درحقیقت آج اسلام کو جس بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں چاروں طرف کفر غالب ہے اور مسلمان جمود اور بے حسّی کا شکار ہیں.ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کی اشاعت کے لئے اس جنون سے کام لیں جس جنون سے قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے کام لیا تھا اور اسلام کو تھوڑے عرصہ میں ہی تمام معلومہ دنیا میں غالب کر دیا تھا پس حج کے ذکر کے
Page 259
ساتھ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ فرما کر میرے نزدیک اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اس عظیم الشان اجتماع سے بعض دوسرے فوائد بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کا وہ فضل تلاش کرو جس کے نتیجہ میں مسلمان قعرِ مذلّت سے نکل کر بامِ عروج پر پہنچ جائیں اور اسلام کی اشاعت کے لئے مختلف ممالک کے با اثر اور ممتاز افراد کے ساتھ مل کر ایسی سکیمیں سوچو جن کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہو جائے اوراسلام دنیا پر غالب آجائے.غرض اس فضل کو تلاش کرنا جس کے نتیجہ میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو اللہ تعالیٰ نے ہمارا فرض قرار دیا ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کا فضل تلاش کرو.یہ کلام کا ایک طریق ہے جس کا مقصد کسی اہم نیکی کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے.اسی طریق کلام کو اس جگہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے اچھے موقعہ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی تلاش نہ کرنا کیا کوئی گناہ کی بات ہے کہ تم اسے چھوڑ رہے ہو.یعنی اس عظیم الشان اجتماع کے موقعہ کو جبکہ دنیا کے چاروں کناروں سے لوگ یہاں جمع ہیں غنیمت جانو اور اسے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو.یہ لَا جُنَاحَ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ لَا جُنَاحَ اَنْ یَّطَّوَّفَ بِھِمَا (البقرۃ :۱۵۹)میں لَاجُنَاحَ کا استعمال کیا گیا ہے.فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.فرمایا جب تم عرفات سے واپس آئو تو مشعرالحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو.عرفات مکّہ سے شمال مشرق کی طرف قریباً نو میل کے فاصلہ پر ایک وسیع میدان ہے جہاں ۹؍ذوالحجہ کو تمام حاجی جمع ہوتے ہیں یہاں ٹھہرنا اور عبادت کرنا اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے اور تمام مناسک ادا کرے مگر عرفات کے میدان میں نہ پہنچ سکے تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا.اور مشعر الحرام مزدلفہ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم عرفات میں عبادت کر چکو اور وہاں سے واپس لوٹو تو مشعرالحرام کے پاس جو مزدلفہ میں ایک پہاڑی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا طریق تھا کہ آپ یہاں بھی دُعا کیا کرتے تھے (مشکٰوة المصابیح کتاب المناسک باب الدّفع من عرفة والمزدلفة)مگر اب عام طور پر لوگ اس جگہ دُعا نہیں کرتے بلکہ اس جگہ کا پتہ لگانے میں بھی دقّت محسوس ہوتی ہے چنانچہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا.ہم نے اس کا پتہ لگانے کی بڑی کوشش کی مگر نہ لگا.اور یونہی دعا کر کے چل پڑے.معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑی پہاڑی نہیں بلکہ ٹیلہ سا ہے.چونکہ وہاں ایسے کئی ٹیلے ہیں اور مجمع بھی بہت ہوتا ہے اس لئے اس کا آسانی سے پتہ نہیں لگ سکتا.اس آیت میں اَفَضْتُمْ کا لفظ استعمال فرما کر اس امر کا بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو تمہارے قلوب اللہ تعالیٰ کی برکات اورا س کے انوار سے اس طرح معمور ہونے چاہئیں جیسا کہ ایک برتن اپنے
Page 260
کناروں تک پانی سے بھراہوا ہوتا ہے.اور پھر اسی حالت میں جبکہ ساقی کو ثر کی روحانی شراب سے تمہارے جام لبالب بھرے ہوئے ہوں تم مشعر الحرام کے پاس پہنچو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو.گویا روحانی انعامات کی وہ بارش جو عرفات میں تم پر نازل ہوئی ہے وہ تمہیں بہاتی ہوئی مشعر الحرام کی طرف لے جائے اور تمہیں اپنے محبوب کے قدموں تک پہنچا دے.وَ اذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْاس کے دو معنے ہیں.ایک یہ کہ اُذْکُرُوْہُ ذِکْرًا کَمَا ھَدٰ لکُمْ اس کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور دوسرے یہ کہ اس کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے.ان معنوں کے لحاظ سے اس جگہ کَمَا کا استعمال ایسا ہی ہے جیسا كَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ(الحجر : ۹۱) میں کیا گیا ہے.وَ اِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ میں اِنْ مخففہ ہے اور اس کے معنے ’’گو‘‘ کے ساتھ ملتے ہیں.فرّاء نے کہا ہے کہ اس کے معنے نفی کے ہیں.اور لام کے معنے اِلَّا کے ہیں.یعنی ’’تم اس ہدایت سے پہلے نہ تھے مگر گمراہ‘‘.کسائی نے کہا ہے کہ اس کے معنے قَدْ کے ہیں اور لام زائد ہے.یعنی تم ضرور اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے.ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ١ؕ اور جہاں سے لوگ(واپس)لوٹتے رہے ہیں وہیں سے تم بھی (واپس) لوٹو اور اللہ (تعالیٰ) سے مغفرت طلب کرو.اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰۰۲۰۰ اللہ یقیناًبہت بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.حل لغات.اَفِیْضُوْا اَفَاضَ یَفِیْضُ سے امر کا صیغہ ہے اور اَفِیْضُوْا مِنْ حَیْثُ اَفَاضَ النَّاسُ کے معنے ہیں دَفَعْتُمْ مِنْھَا بِکَثْرَۃٍ تَشْبِیْھًا بِفَیْضِ الْمَآءِ.یعنی تم وہاں سے کثرت سے چل پڑو.یہ معنے پانی کے کثرت سے بہنے کے ساتھ بطور تشبیہ کے ہیں.(مفرداتِ راغب) تفسیر.اس آیت کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ افاضہ تو ہو چکا پھر یہ کونسا نیا افاضہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی عرفات سے تو لوٹ آئے پھر اور کہاں سے لوٹنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ ثُمَّ کے معنے ’’اور‘‘ کے ہیں.اور اس بات کو اس لئے دہرایا ہے کہ پہلے اس بارہ میں کوئی حکم نہ تھا بلکہ صرف اظہار واقعہ کیا گیا تھا.اب حکم دیا کہ جہاں سے دوسرے لوگ واپس لوٹتے رہے ہیں وہیں سے تم بھی لوٹو.اور یہ حکم اس
Page 261
لئے دیا گیا ہے کہ قریش اور ان کے ساتھیوں کا طریق تھا کہ وہ مزدلفہ سے آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے.بلکہ مزدلفہ ہی سے واپس چلے آتے تھے.اور اس کی وجہ وہ یہ قرار دیتے تھے کہ عرفات حدودِ حرم سے باہر ہے اس لئے ہم وہاں نہیں جائیں گے بلکہ مزدلفہ میں مشعرالحرام کے پاس ہی ٹھہریں گے جو حرم کے اندر ہے اور کہتے کہ ہم حرم کے باشندے ہیں اس لئے ہم حرم سے باہر نہیں جا سکتے.لیکن دوسرے قبائل عرفات میں جا کر حج کرتے تھے.اس لئے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح دوسرے لوگ عرفات میں جاتے اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں اسی طرح تم بھی وہاںجائو اور جس طرح وہ عرفات سے واپس آتے ہیں اسی طرح تم بھی واپس آئو.لیکن اگر ثُمَّ کے معنے ’’پھر‘‘ یا ’’تب‘‘ کے کئے جائیں تو اس صورت میں اس کا یہ مطلب ہو گا.کہ پھر تم مزدلفہ سے لوٹو جہاں سے سب لوگ واپس لوٹتے رہے ہیں.یہاں تک کہ قریش اور بنو کنانہ جو حُمس یعنی بڑے پکے دیندار کہلاتے تھے وہ بھی یہیں سے واپس چلے جاتے تھے.مزدلفہ سے لوٹنے کے متعلق یہ حکم ہے کہ تمام حاجی نماز پڑھ کر اور دُعا کر کے سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے چلیں اور منیٰ میں سورج نکلنے کے بعد پہنچ جائیں.جہاں رمی جمار کی جاتی ہے.قربانیاں دی جاتی ہیں اور احرام کی حالت ختم ہو جاتی ہے.یہ آیت چکڑالویوں پر بھی حجّت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود اس جگہ کا نام نہیں بتایا.پس تفسیر کےلئے سنت کا تفحص بھی ضروری ہے.پھر فرماتا ہے وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.تم ان مناسک کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہو کیونکہ حج ایک بہت بڑا ابتلاء بھی ہے.مجھ سے کئی لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے حج کیا اور ہمار ادل پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا.اسی طرح بہت سے لوگوں نے بیان کیا کہ حج کے دنوں میں تو بڑا جوش ہوتا ہے مگر بعد میں دل پر بُرا اثر پڑتا ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حج میں ظاہر پر اس قدر زور ہے کہ اس کے مقابلہ میں باطن بہت حد تک پوشیدہ ہو جاتا ہے.مثلاً وہاں حجرِ اسود کو بوسہ دیتے ہیں.صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں.بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں.منیٰ میں تین ٹیلوں پر جو اب برجیوں کی شکل میںہیں کنکر پھینکتے ہیں.اس لئے اگر ساتھ ساتھ استغفار نہ ہو تو دل پر زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح وہاں پانچ پانچ گھنٹے بیٹھ کر عبادت کرنی پڑتی ہے.ہزاروں کے مجمع میں مَیں نے ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جو دُعا کرتا ہو.لوگ حج صرف اس قدر سمجھتے ہیں کہ خطیب جب کھڑا ہو تو اس کے رومال کے ساتھ رومال ہلا دیں.مگر مجھے خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور میں نے وہاں کثرت سے دُعائیں کیں.تو چونکہ یہ نماز کی طرح ایک معیّن عبادت نہیں اس لئے لوگ اس کی اہمیت محسوس نہیں کرتے.شریعت
Page 262
نے صرف ظاہر بتا دیا ہے اور باطن کو انسان پر چھوڑ دیا ہے.مگر وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ ہم نے یہاں دُعا یا عبادت کرنی ہے.پس فرماتا ہے.حج کے ایام میں تمہیں استغفار کی سخت ضرورت ہے.کیونکہ حج میں ظاہر زیادہ نمایاں ہے اور باطن جو جوہر عبادت ہے مخفی ہے.اگر انسان باطن کی طرف توجہ نہ کرے اور صرف ظاہر پر عمل کر کے سمجھ لے کہ اس نے شریعت کی اصل غرض کو پورا کر دیا ہے.تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے.فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ پھر جب تم اپنی عبادتیں پوری کر چکو تو (گذشتہ زمانہ میں) اپنے باپ دادوں کو یاد کرنے کی طرح اللہ کو یاد کرو.اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا١ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ یا(اگر ہوسکے تو اس سے بھی )زیادہ (دلبستگی سے) یاد کرو اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو (یہی ) کہتے رہتے ہیں کہ اے اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۰۰۲۰۱وَ مِنْهُمْ ہمارےرب! ہمیں اس دنیا میں (آرام) دے اور ان کا آخرت میں کچھ بھی حصّہ نہیں ہوتا.اور ان میں سے کچھ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ (ایسے بھی ہوتے )ہیں جو کہتے ہیںکہ اے ہمارے رب!ہمیں (اس) دنیا (کی زندگی) میں (بھی) کامیابی دے حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ۰۰۲۰۲ اور آخرت میں(بھی) کامیابی (دے) اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا.حلّ لُغات.اَوْ کے معنے ’’ یا‘‘ کے بھی ہوتے ہیں اور یہ لفظ اظہار ترقی کے لئے بھی آتا ہے.اسی طرح اَوْکا لفظ کسی چیز کو حقیر ظاہر کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے(بحر محیط).اَشَدَّ یہ ذکر کی صفت ہے جو بطور حال پہلے بیان کر دی گئی ہے.تفسیر.فرماتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق حج بیت اللہ کا فرض ادا کر چکو تو خدا تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو.اہل عرب میں دستور تھا کہ جب وہ حج
Page 263
سے فارغ ہو جاتے تو تین دن منیٰ میں مجالس منعقد کر کے اپنے باپ دادوں کے کارنامے بیان کرتے اور اپنے اپنے قبیلہ کی بہادری شہرت اور سخاوت کی تعریف میں قصیدے پڑھتے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ تو اپنے باپ دادوں کی تعریف میں قصائد پڑھا کرتے تھے مگر ہم تمہیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ جب تم مناسک حج کو ادا کر چکو تو تم خدا تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو.یعنی جس طرح ایک چھوٹا بچہ جو اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے روتا اور چلّاتا ہوا کہتا ہے کہ میں نے اپنی اماں کے پاس جانا ہے اسی طرح تم بھی بار بار خدا تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ اس کی محبت تمہارے رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے.خدا تعالیٰ ایک وراء الوراء ہستی ہے اس کا حسن براہ راست انسان کے سامنے نہیں آتا بلکہ کئی واسطوں کے ذریعہ سے آتا ہے.اگر اُس کے حسن کو الفاظ میں بیان کیا جائے اور پھر ہم اس پر غور کریں اور سوچیں تو آہستہ آہستہ معنوی طور پر اس کی شکل ہمارے سامنے آجاتی ہے.اگر تم مالک کا نام لو اور اس کی مالکیت کو ذہن میں لائو.قدوس کا نام لو اور اس کی قدوسیت کو ذہن میں لاؤ.ستّار کا نام لو اور اس کی ستاریت کو ذہن میں لائو.غفور کانام لو اور اس کی غفوریت کو ذہن میں لائو تو یہ لازمی بات ہے کہ آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کی ایک مکمل تصویر تمہارے سامنے آجائےگی.اور محبت کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ یا تو کسی کا وجود سامنے ہویا اس کی تصویر سامنے ہو.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے ایک شعر میں اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں.؎ دیدار گر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی حسن و جمال یار کے آثار ہی سہی یعنی اگر محبوب خود سامنے نہیں آتا تو اس کی آواز تو سنائی دے اور اس کے حُسن کی کوئی نشانی تو نظر آئے.پس ربّ، رحمٰن ، رحیم، مالک یوم الدین، ستار، غفار، قدوس، مہیمن، سلام، جبار، قہار اور دوسری صفاتِ الٰہیہ کو جب ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی ایک تصویر ہمارے سامنے آجاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے.غرض صفاتِ الٰہیہ کے باربار دُہرانے اور تواتر سے دُہرانے کے نتیجہ میں چونکہ خدا تعالیٰ کی ایک تصویر بنتی ہے اور اس تصویر کی وجہ سے ہی ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح بچوں کے دل میں اپنے ماں باپ کی ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے.اسی طرح تمہارابھی خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی روحانی تعلق ہونا چاہیے.گویا تمہارا چین اور تمہارا آرام صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی وابستہ ہونا چاہیے کیونکہ اسی پر تمہاری روحانی زندگی کا مدار ہے.اور حج کے بعد ذکر الہٰی کی طرف توجہ دلا کر اس
Page 264
طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تمہارا خدا تعالیٰ سے اب ایک روحانی پیوند قائم ہو چکا ہے.پس جس طرح ایک بچہ اپنے ماں باپ کے سایہ عاطفت میں اپنی زندگی کے دن بسر کرتا ہے اور ان کے اخلاق و عادات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح تم بھی خدا تعالیٰ کی صفات کا آئینہ بنو اور اسی کے سایہ عاطفت میں اپنی زندگی کے دن بسر کرو.پھر فرماتا ہے اَوْ اَشَدَّ ذِکْرًا ہم نے پہلے تو تمہیں یہ ہدایت دی ہے کہ تم خدا تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو.مگر ہمارا یہ حکم صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو روحانیت میں ابھی اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچے ورنہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی محبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہاتھ پوشیدہ دیکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں ماں باپ کے تعلق کو بالکل ہیچ سمجھتے ہیں.ان کو چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا ایسے رنگ میں ذکر کریں کہ ان کے دنیوی تعلقات میں اس کی کوئی مثال دکھائی نہ دے اور ماںباپ کا ذکر اس کے مقابلہ میں بالکل ہیچ ہو جائے.فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں.جیسے عیسائی ہیں.وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ ’’ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے‘‘(متی باب۶ آیت ۱۱) انہیں حرام و حلال سے کوئی غرض نہیں ہوتی.انہیں کسی چیز کے مفید یا مضر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.ان کا مطمح نظر محض دنیا طلبی ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا کے ساتھ حَسَنَۃً کا لفظ استعمال نہیں کیا.جس میں یہ اشارہ ہے کہ ایسے لوگ صرف دنیا پر جان دیتے ہیں حالانکہ خالی دنیوی عزت جس کے ساتھ اخروی عزت نہ ہو ایک لعنت ہوتی ہے.جیسے یہود کو آجکل خالی دنیوی عزت ملی ہوئی ہے.اسی طرح عیسائیوں کو صرف دنیوی عزت ملی ہوئی ہے مگر اُخروی عزت سے انہیں کوئی حصہ نہیں ملا.اسی لئے فرمایا کہ وَ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں.یعنی ہم انہیں دنیا تو دے دیتے ہیں مگر اُخروی انعامات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا.لیکن دوسری طرف خالی اُخروی عزت بھی ایک بے ثبوت چیزہوتی ہے.ثبوت والی چیز وہی ہوتی ہے جس میں دین اور دنیا دونوں اکٹھے ملیں.اسی لئے فرمایا کہ ایک اور گروہ ایسا ہے جو یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ یعنی الٰہی! ہمیں دنیا میں بھی عزت بخش اور آخرت میں بھی ہمارے مقام کو بلندکر.اگر ہمیں دنیا ملے تو ہم اسے اپنی ذات کے لئے استعمال نہ کریں بلکہ تیرے دین کی شوکت ظاہر کرنے کےلئے استعمال کریں اور تیری رضا اور خوشنودی کے لئے اُسے صرف کریں.اگر ایسا ہو تو پھر انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور خدا تعالیٰ کے حضور بھی اس کا مرتبہ بڑھتا ہے.یہ دُعا جو اسلام نے ہمیں سکھائی
Page 265
ہے بظاہر بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن ہر قسم کی انسانی ضرورتوں پر حاوی ہے.انسان کہتا ہے رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً اے ہمارے رب !ہم کو اس دنیا میں حسنہ دے.بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حسنہ کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے یہ درست نہیں.حسنات کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا جس کے معنے بہت سی نیکیوں کے ہیں مگر یہ اعتراض عربی زبان سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے.اصل بات یہ ہے کہ اگر یہاں حسنات کا لفظ ہوتا تو اس کے معنے یہ ہوتے کہ ہمیں کچھ اچھی چیزیں ملیں لیکن حسنہ کے یہ معنے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملے خیر ہی ملے.پس رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةًکے یہ معنے ہیں کہ اے ہمارے رب! دنیا میں ہم کو جو کچھ دے حسنہ دے.روٹی دے تو حلال ہو طیب ہو، پچنے والی ہو.کپڑا دے تو حلال دے طیّب دے، ضرورت کے مطابق دے، ننگ ڈھانکنے والا دے، پسندیدہ دے، بیوی دے تو ایسی دے جو ہمدرد ہو ہم خیال ہو دیندار ہو محبت کرنے والی ہو، نیکی میں تعاون کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو،ان بچوں کی نیک تربیت کرنے والی ہو، مکان دے تو مبارک ہو، وہ بیماریوں والا گھر نہ ہو، سل دق اور ٹائیفائیڈ کے جراثیم اس میں نہ ہوں، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو صحت پر بُرا اثر کرنے والی ہو، کوئی ہمسایہ ایسا نہ ہو جو دکھ دینے والا ہو، وہ ایسے محلہ میں نہ ہو جہاں کے رہنے والے بُرے ہوں، وہ ایسے شہر میں نہ ہو جسے تو میرے لئے اچھا نہ سمجھتا ہو، ہمیں حاکم دے تو ایسے دے جو رحم د ل ہوں، تقویٰ سے کام لینے والے ہوں، انصاف سے کام لینے والے ہوں، ماتحتوں سے محبت کرنے والے ہوں ، ہمیں اُستاد دے تو ایسے دے جو علم رکھنے والے اور اچھا پڑھانے والے ہوں، وہ شوق سے پڑھائیں وہ ظالم نہ ہوں، خرابیاں پیدا کرنے والے اور دوسروں کو ورغلانے والے نہ ہوں، دوست دے تو ایسے دے جو خیرخواہ ہوں،محبت کرنے والے ہوں، مصیبت میں کام آنے والے ہوں، خوشی میں شریک ہونے والے ہوں، دکھوں میں ہاتھ بٹانے والے ہوں، غرض رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً اے ہمارے رب! دنیا میں ہم کو وہ چیز دے جو حسنہ ہو.پس یہاں حسنات کی بجائے حسنہ کا لفظ رکھ کر اس کے مفہوم کو خدا تعالیٰ نے وسیع کر دیا ہے.اور جب مومن یہ دعا کرتا ہے تو دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہتا ہے کہ خدایا !مجھے ہر وہ چیز دے جو میری ضرورت کے مطابق ہو اور پھر وہ چیز ایسی ہو جو نہایت اچھی ہو مگر اچھی چیزکے لئے اور الفاظ بھی استعمال ہو سکتے تھے.خدا تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال نہیں کئے بلکہ حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے اس لئے یہ لفظ ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں پر دلالت کرتا ہے ہوسکتا ہے کہ ایک چیز اپنے فوائد اور خوبیوں کے لحاظ سے اچھی ہو مگر ظاہری صورت کے لحاظ سے اچھی نہ ہو.مثلاً کسی شخص کی بیوی بڑی بااخلاق ہو.مگر فرض کرو وہ نکٹی ہے یا اندھی ہے یا بہری ہے تو وہ حسنہ نہیں کہلائےگی حسنہ وہی بیوی کہلائےگی جس کے اخلاق بھی اچھے ہوں شکل بھی اچھی ہو ظاہر بھی اچھا ہو
Page 266
اور باطن بھی اچھا ہو.تو حسنہ کا لفظ ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں پر دلالت کرتا ہے.اور مومن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے جو چیز بھی دے وہ ایسی ہو جو ظاہری اور باطنی دونوں خوبیاں رکھتی ہو.پھر فرمایا وَفِیْ الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً آخرت میں بھی ہمیں وہ چیز دے جو حسنہ ہو.یعنی وہ بھی ظاہر و باطن میں ہمارے لئے اچھی ہو.ممکن ہے کوئی کہے کہ آخرت میں تو ہر چیز اچھی ہوتی ہے.وہاں کی چیزوں کے لئے حسنہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے.آخرت میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو باطن میں اچھی ہیں مگر ظاہر میں بُری ہیں.مثلاً دوزخ ہے.قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ انسان کی اصلاح کا ذریعہ ہے.پس ایک لحاظ سے وہ اچھی چیز ہے.مگر ایک لحاظ سے وہ بُری بھی ہے.پس جب آخرت کے لئے خدا تعالیٰ نے حسنہ کا لفظ رکھا تو اس لئے کہ تم یہ دُعا کرو کہ الہٰی ہماری اصلاح دوزخ سے نہ ہو بلکہ تیرے فضل سے ہو.اور آخرت میں ہمیں وہ چیز نہ دیجیئو جو صرف باطن میں ہی اچھی ہو.جیسے دوزخ باطن میں اچھا ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے مگر ظاہر میں بُرا ہےکیونکہ وہ عذاب ہے.آخرت میں حسنہ صرف جنت ہے.جس کا ظاہر بھی اچھا ہے اور جس کا باطن بھی اچھا ہے.پھر فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.ہم کو عذاب نار سے بچا.اس سے مراد وہی عذاب نار نہیں جو مرنے کے بعد ملے گا.یہ عذاب نار دنیا کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی دُعائوں کے بعد وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کہا گیا ہے.پس وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کے معنے یہ ہیں کہ ہمیں دنیا کے عذاب نار سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب نار سے بھی محفوظ رکھ.ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی لوگ عذاب نار میں گرفتار ہوتے ہیں.انہیں کئی قسم کے دُکھ ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، حسرتیں ہوتی ہیں،قسم قسم کے مصائب ہوتے ہیں مگر جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ خدایا! مجھے عذاب نار سے بچا.تو خدا تعالیٰ اُسے اس عذاب سے بچا لیتا ہے.تب وہ چیزیں جو پہلے اس کے لئے نار تھیں جنت بن جاتی ہیں.اسی طرح اس سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے جس سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دُعا سکھلائی ہے.بظاہر یہ ایک مختصر سی دُعا ہے مگر بڑی جامع اور وسیع دعا ہے.عَذَابَ النَّارِ کے لحاظ سے دنیا کی لڑائی بھی مراد لی جا سکتی ہے.کیونکہ لڑائی بھی آگ کا ہی عذاب ہے.پس جو شخص یہ دُعا کرے گا کہ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.وہ گویا خدا تعالیٰ کے بیان فرمودہ الفاظ میں یہ دعا کرے گا کہ الٰہی! دنیا میں مجھ پر کوئی ساعت ایسی نہ آئے جو بُری ہو.لڑائی مجھ سے دُور
Page 267
رہے اوریہ آگ کا عذاب میرے قریب نہ پہنچے.اگر کوئی سپاہی لڑائی میں شامل ہو اور وہ یہ دُعا کرے.تو اس کی دُعا کے یہ معنے ہوںگے کہ اس لڑائی کے بد اثرات سے مجھے بچا.بندوق کی گولی آئے تو وہ مس کر جائے.میرے دائیں نکل جائے یا بائیںنکل جائے.اوپر نکل جائے یا نیچے نکل جائے.بہر حال وہ مجھے نہ لگے.اور میں اس سے محفوظ رہوں پس یہ ایک جامع دُعا ہے جو اسلام نے سکھائی ہے اور جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بڑی کثرت سے پڑھا کرتے تھے.اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا١ؕ وَ اللّٰهُ یہی (وہ لوگ )ہیں جن کے لئے ان کی (نیک) کمائی کے سبب سے (ثواب کا) ایک بہت بڑا حصّہ (مقدر) ہے سَرِيْعُ الْحِسَابِ۰۰۲۰۳ اور اللہ (بہت) جلد حساب چکا دیتا ہے.تفسیر.کَسَبَ کے معنے محنت کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کے ہوتے ہیں لیکن اس جگہ کَسَبُوْا کا لفظ اوپر والی دُعا کے لئے استعمال کیا گیا ہے.اور کہا گیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کمایا اس سے ان کو حصہ ملے گا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسب کا لفظ زبان یا دل کے فعل پر بھی بولا جاتا ہے اور مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی نعماء طلب کرتے رہتے ہیں وہ اپنے اپنے اخلاص اور ایمان کے مطابق خدا تعالیٰ سے اجر پائیں گے.وَ اللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بدی کی جزا میں کوئی دیر نہیں لگتی بلکہ ادھر عمل سرزد ہوتا ہے اور ادھر اس کی جزا ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کا ہر عمل اس کے جوارح پر فوراً اثر ڈال دیتا ہے.یہ مضمون قرآن کریم میں کئی جگہ بیان ہوا ہے اور حدیثوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص بُرا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اس کے بد اعمال بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے.اور جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے اور جب اس کے بعد وہ متواتر نیک اعمال بجا لاتا ہے تو یہ سفید نقطے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یہا ں تک کہ اس کا سارا دل منور ہو جاتا ہے.(مسند احمد بن حنبل ،مسند بریرہؓ)
Page 268
سَرِيْعُ الْحِسَابِ میں اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر کام کا اثر فوراً انسان کے دل پر پڑجاتا ہے.اور یہ بھی ایک قسم کا حساب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جاتا ہے.تازہ تحقیقات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی انسانی حرکت ایسی نہیں جو فضا میں محفوظ نہ ہوجاتی ہو پس عمل اور اس کی جزایہ دو توام بھائی ہیں کہ ایک کے ساتھ دوسرا بھی ظہور میں آجاتا ہے.وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْۤ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ١ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ اور(ان) مقررہ دنوں میں اللہ (تعالیٰ ) کو یاد کرو.پھر جو شخص جلدی کرے (اور) يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ١ۚ وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ١ۙ دو دنوں میں (ہی واپس چلاجائے ) تو اسے کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اسے (بھی) کوئی گناہ نہیں (یہ وعدہ) لِمَنِ اتَّقٰى١ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اس شخص کے لئے ہے جو تقویٰ اختیار کرےاور تم اللہ(تعالیٰ) کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ (ایک دن) تم سب کو اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ۰۰۲۰۴ اکٹھا کر کے اس کے حضور لے جایا جائے گا.تفسیر.اس آیت میں جن مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے وہ ایام تشریق ہیں یعنی ۱۱.۱۲.۱۳ ذوالحجہ یا ایام منیٰ ہیں.جو دسویں تاریخ سے شروع ہوتے ہیں اور ۱۳ کو ختم ہو جاتے ہیں.فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ.فرماتا ہے جو شخص جلدی کرے اور دو دنوں میں ہی واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں.دراصل دسویں ذوالحجہ کے بعد رمی الجمار کے لئے تین دن رکھے گئے ہیں.مگر اجازت ہے کہ کوئی شخص دو دن کے بعد بھی لوٹ آئے.اس بارہ میں امام ابو حنیفہ ؒ کا مذہب تو یہ ہے کہ ایام تشریق کے تیسرے دن صبح کے وقت جا سکتا ہے.لیکن بعض نے کہا ہے کہ دوسرے دن رمی الجمار کے بعد بھی جا سکتا ہے.بعض نے کہا ہے
Page 269
کہ اگر عصر کا وقت آجائے تو نہیں جا سکتا.اس سے پہلے جا سکتا ہے.گویا اس سے تیسرے دن کی رمی معاف ہو گئی.پھر بعض نے کہا ہے کہ جس نے تعجیل کی نیت کی اسے چاہیے کہ وہ یوم النحر کو رمی کرے(بحر محیط زیر آیت ھذا).پھر فرماتا ہے وَ مَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى.اور جو شخص پیچھے رہ جائے یعنی تیسرے دن رمی کر کے جائے.اسے بھی کوئی گنا ہ نہیں اور یہ وعدہ اس شخص کےلئے ہے جو تقویٰ اختیار کرے.بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ لِمَنِ اتَّقٰى کا تعلق تعجیل کے ساتھ ہے مگر میرے نزدیک اس کا تعلق نہ تعجیل کے ساتھ ہے نہ تاخیر کے ساتھ بلکہ لَا اِثْمَ عَلَیْہِ کے ساتھ ہے ورنہ جو گناہ گار ہے وہ تو گناہ گار ہی ہے اس کے متعلق لَا اِثْمَ عَلَیْہِ کہنا تو درست ہی نہیں ہو سکتا.یہ نفیِ اِثْم صرف ایسے شخص کے لئے ہے جو متقی ہو.یعنی اگر وہ کسی اور طرح گنہگار نہیں تو اس تعجیل یا تاخیر سے گنہگار نہیں ہوتا.آخر میں وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ ان مناسک کی اصل غرض یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو.تمہارا بیت اللہ کا طواف کرنا.حجراسود کو بوسہ دینا.صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا.مزدلفہ منیٰ عرفات اور مشعرا لحرام میں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرنا.اور رمی الجمار کرنا.یہ سب اس غرض کے لئے ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت پیدا ہو اور تم سمجھو کہ ایک دن تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہونے والے ہو.پس اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا اور اس کی راہ میں ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کیا اور کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ اور اسمٰعیل ؑ اور ہاجرہ ؑ کو برکت دی تھی.اُسی طرح وہ تمہیں بھی برکت عطا فرمائے گا اور تمہاری نسلوں کو بھی اپنی دائمی حفاظت اور پناہ میں لے گا.پس تقویٰ کو اپنا شعار بنائو اور اس دن کو یاد رکھو جب تم سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی کے لئے خدا تعالیٰ کےحضور حاضر ہونا پڑےگا.حج کے احکام تو ختم ہو گئے مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جگہوں میں جانے اور وہاں چکر لگانے کی کیا حکمتیں ہیں؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے نزدیک اس کی ظاہری حکمتوں میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ َ(آل عمران :۹۷) کہ سب سے پہلا گھر جو تمام دنیا کے فائدہ کے لئے بنایا گیا تھا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا بلکہ یہ آدم کے زمانہ سے چلا آتا ہے (خواہ وہ کوئی آدم ہو) پس وُضِعَ لِلنَّاسِ میں پیشگوئی تھی کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اسے ساری دُنیا کو اکٹھا کرنے کے لئے بنایا ہے اس لئے تمام لوگوں کو اس جگہ جمع کیا جائےگا چنانچہ اسی غرض کے لئے حج کی خاص
Page 270
تاریخیں مقرر کر دی گئیں.تاکہ ان تاریخوں میں وہاں ساری دنیا کے لوگ جمع ہو سکیں.گویا دوسرے الفاظ میں تمام دنیا کو اکٹھا کرنے اور جہان بھر کے اتقیاء او ر صلحاء کو جمع کرنے اور عالم اسلامی میں عالم گیر اخوت اور اتحاد پیدا کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنے مائدہ روحانی پر لوگوں کو ایک عظیم الشان دعوت دی ہے تاکہ قومی اور ملکی منافرت درمیان سے اُٹھ جائے اورباہمی تعلقات وسیع ہو جائیں.اور ایک دوسرے کی محبت ترقی کرے.اور یہ خیال کہ ہم فلاں قوم سے ہیں اور ہمار اغیر فلاں قوم سے ہے مٹ جائے.میرے نزدیک منیٰ میں لوگوں کے تین دن اسی لئے فارغ رکھے گئے ہیں کہ وہاں لوگ ذکر الہٰی اور عبادت میں اپنا وقت گذارنے کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے سے ملیں اور حالات معلوم کریں.قادیان اور ربوہ میں بھی لوگ مختلف اوقات میں آتے رہتے ہیں.مگر وہ تعلقات نہیں بڑھتے جو جلسہ سالانہ کے ایام میں بڑھتے ہیں.اگر حج سے یہ فائدہ اُٹھانے کی کوشش کی جائے تو میرے نزدیک وہ تفرقے اور شقاق مٹ سکتے ہیں.جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور کر رکھا ہے اور ان کے درمیان اختلافِ عقائد کے باوجود زبردست اتحاد پیدا ہو سکتا ہے غرض حج گو ایک مذہبی عبادت ہے مگر اس میں روحانی فوائد کے علاوہ یہ ملی اور سیاسی غرض بھی ہے کہ مسلمانوں کے ذی اثر طبقہ میں سے ایک بڑی جماعت سال میں ایک جگہ جمع ہو کر تمام عالم کے مسلمانوں کی حالت سے واقف ہوتی رہے.اور ان میں اخوت اور محبت ترقی کرتی رہے اور انہیں ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہونے اور آپس میں تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو اخذ کرنے کا موقعہ ملتا رہے.گو افسوس ہے کہ اس غرض سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاتا.یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حج سے یہی غرض تھی تو پھر مکہ مکرمہ میں ہی تمام مسلمانوں کا اجتماع کافی تھا عرفات منیٰ اور مزدلفہ میں جانے کی کیا غرض ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ عرفات منیٰ اور مزدلفہ میں جمع کرنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ شہر میں اجتماع کی صورت نہیں ہوسکتی اور نہ لوگوں کا آپس میں صحیح رنگ میں میل جول ہو سکتا ہے.اس لئے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھلے میدانوں میں جمع ہونے کا حکم دےدیا تاکہ وہاں لوگ آسانی سے ایک دوسرے سے مل سکیں چونکہ جگہ بھی کھلی ہوتی ہے او ر وقت بھی فارغ ہوتا ہے اس لئے ایک دوسرے کو ملنے کا مدّعا خوب اچھی طرح پورا ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ خدا تعالیٰ نے مزدلفہ منیٰ اور عرفات کو اس شرف کے لئے اس لئے چُنا ہے کہ عرفات ساحل سمندر کی طرف ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی راستہ سے حضرت ہاجرہؓ اوراسمٰعیل ؑ کو چھوڑنے کے لئے شام سے تشریف لائے تھے.اور عرفات وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ان پر تجلی ظاہرہوئی.اور مزدلفہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے یہ وعدہ کیا گیاکہ اس قربانی کے بدلہ میں تجھے بہت بلند
Page 271
درجات عطا کئے جائیںگے اور منیٰ وہ مقام ہے جہاں حضرت ہاجرہ ؑ گھبرائی ہوئی پہنچی تھیں مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تمہیں یہاںچھوڑ کر جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اِذًا لَّا یُضَیِّعُنَا (بخاری کتاب الانبیاء باب یزفون النسلان فی المشی ) اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور وہ واپس چلی گئیں.گویا شیطان ہمیشہ کے لئے مار دیا گیا.اس لئے یہاں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں.پھر حج بیت اللہ کی ایک غرض شعائر اللہ کا احترام اور ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم کرنا ہے.شعائر اللہ کے لفظ سے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں.چونکہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن صرف ظاہر سے باطن کی طرف منتقل ہوا کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ میں ان کے سامنے ایسے نشانات رکھ دیئے جو خدا تعالیٰ کو یاد دلانے والے اور اس کی محبت دلوں میں تازہ کرنے والے ہیں.حج دراصل اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ کر تا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ ؑ او راسمٰعیل ؑ کو بیت اللہ کے قریب ایک وادی غیر ذی زرع میں انتہائی بے سروسامانی کی حالت میں چھوڑ کر سرانجام دی تھی بعض لوگ غلطی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے بچے حضرت اسمٰعیلؑ کی گردن پر چھُری پھیرنے کےلئے تیار ہو گئے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد گار حج کی صورت میں قائم کر دی.حالانکہ اگر یہ درست ہوتا تو چونکہ یہ واقعہ شام میں ہوا تھااس لئے حج کا اصل مقام شام ہوتا نہ کہ حجاز اور لوگ وہاں جمع ہو کر خدا تعالیٰ کی یاد کرتے اور کہتے ابراہیم ؑنے کس قدر قربانی کی تھی! لیکن خدا تعالیٰ نےحج کےلئے مکہ مکرمہ کو چُنا اور منیٰ اور مزدلفہ اور عرفات میں جانا اور وہاں مناسک حج بجا لانا ضروری قرار دیا.پس میرے نزدیک حج کا تعلق آپ کا چُھری پھیرنے کےلئے تیار ہو جانےوالے واقعہ سے نہیں بلکہ اس واقعہ سے ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ ؑ اور اسمٰعیل ؑ کو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک ایسی وادی میں لا کر پھینک دیا جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہ تھا اور کھانے کے لئے ایک دانہ تک نہ تھا جب انسان حج کے لئے جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے یہ نقشہ آجاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے لئے قربانی کرنے والے بچائے جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی عزت دیتا ہے اور حج کرنے والے کے دل میں بھی خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی اور اس کی ذات پر یقین ترقی کرتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو اس گھر میں دیکھ کر جو ابتدائے دنیا سے خدا تعالیٰ کی یاد کے لئے بنایا گیا ہے ایک عجیب روحانی تعلق ان لوگوں سے محسوس کرتا ہے جو ہزاروں سال پہلے سے اس روحانی سلک میں پروئے چلے آتے ہیں جس میں یہ شخص پرویا ہوا ہے.یعنی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت کا رشتہ جو سب کو باندھے ہوئے ہے خواہ وہ پرانے ہوں یا نئے اسی طرح بیت اللہ کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کا نقشہ
Page 272
انسانی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے.اور اسے احساس ہوتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر چاروں طرف سے لوگوں کو اس گھر کے گرد جمع کر دیا ہے.جب انسان بیت اللہ کو دیکھتا ہے اور اس پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کے دل پر ایک خاص اثر پڑتا ہے اور وہ قبولیت دعا کا ایک عجیب وقت ہوتا ہے.حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے حج کیا تو میں نے ایک حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ جب پہلے پہل خانہ کعبہ نظر آئے تو اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے.فرمانے لگے اس وقت میرے دل میںکئی دعائوں کی خواہش ہوئی لیکن میرے دل میں فوراً خیال پیدا ہوا کہ اگر میں نے یہ دعائیں مانگیں اور قبول ہو گئیں.اور پھر کوئی اور ضرورت پیش آئی تو پھر کیا ہو گا پھر تو نہ حج ہو گاا ور نہ یہ خانہ کعبہ نظر آئےگا.کہنے لگے تب میں نے سوچ کر یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ یا اللہ! میں جو دعا کیا کروں وہ قبول ہوا کرے.تاکہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے.میں نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے یہ بات سنی ہوئی تھی.جب میں نے حج کیا تو مجھے بھی وہ بات یاد آگئی.جونہی خانہ کعبہ نظر آیا ہمارے نانا جان نے ہاتھ اُٹھائے کہنے لگے دُعا کر لو.وہ کچھ اور دُعائیں مانگنے لگ گئے مگر میں نے تو یہی دُعا کی کہ یا اللہ! اس خانہ کعبہ کو دیکھنے کا مجھے روز روز کہاں موقعہ ملے گا.آج عمر بھر میں قسمت کے ساتھ موقع ملا ہے پس میری تو یہی دُعا ہے کہ تیرا اپنے رسول سے وعدہ ہے کہ اس کو پہلی دفعہ حج کے موقعہ پر دیکھ کر جو شخص دعا کرےگا وہ قبول ہو گی.میری دُعا تجھ سے یہی ہے کہ ساری عمر میری دُعائیں قبول ہوتی رہیں.چنانچہ اس کے فضل اور احسان سے میں برابر یہ نظارہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ہر دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ شاید کسی اعلیٰ درجہ کے شکاری کا نشانہ بھی اس طرح نہیں لگتا.اسی طرح بیت اللہ کے گرد چکر لگاتے وقت جب انسان دیکھتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور ہزاروں ہی اس کے گرد نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں دنیا سے کٹ کر خدا تعالیٰ کی طرف آگیا ہوں اور میرا بھی اب یہی کام ہے کہ میں اس کے حضور سربسجود رہوں.پھر سعی بین الصفا و المروۃ میں حضرت ہاجرہ ؑ کا واقعہ انسان کے سامنے آتا ہے اور اس کا دل اس یقین سے بھر جاتا ہے کہ انسان اگر جنگل میں بھی خدا تعالیٰ کے لئے ڈیرہ لگا دے تو خدا تعالیٰ اُسے کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے خود اپنے پاس سے سامان مہیا کرتا اور اُسے معجزات اور نشانات سے حصہ دیتا ہے پھر وہاں جتنے مقام شعائر کا درجہ رکھتے ہیں ان کے بھی ایسے نام رکھ دیئے گئے ہیں کہ جن سے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیداہوتی ہے مثلاً سب سے پہلے لوگ منیٰ میں جاتے ہیں یہ لفظ اُمْنِیَّۃ سے نکلا ہے جس کے معنے آرزو اور مقصد کے ہیں اور اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ لوگ اس جگہ محض
Page 273
خدا کو ملنے اور شیطان سےکامل نفرت اور علیحدگی کا اظہار کرنے کے لئے جاتے ہیں.پھر عرفات ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں خدا تعالیٰ کی پہچان اور اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے اور ہم اس سے مل گئے ہیں.اس کے بعد مزدلفہ ہے جو قرب کے معنوں پر دلالت کرتا ہے اور جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ مقصد جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے قریب آ گیا ہے.اسی طرح مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مخلصانہ عقیدت اور ابراہیم کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا کرتی ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم خاص طور پر دعائیں فرمایا کرتے تھے.پھر مکہ مکرمہ ایسی جگہ ہے جہاں سوائے چند درختوں اور اذخر گھاس کے اور کچھ نہیں ہوتا.ہر جگہ ریت ہی ریت اور کنکر ہی کنکر ہیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں ہیں.غرض وہ ایک نہایت ہی خشک جگہ ہے نہ کوئی سبزہ ہے نہ باغ دنیا کی کشش رکھنے والی چیزوں میں سے وہاں کوئی بھی چیز نہیں.پس وہاںجانا صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے قرب اور رضا کے لئے ہی ہو سکتا ہے اور یہی غرض حج بیت اللہ کی ہے پھر احرام باندھنے میں بھی ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ کہ انسان کو یوم الحشر کا اندازہ ہو سکے کیونکہ جیسے کفن میں دو چادریں ہوتی ہیں.احرام میں بھی دو ہی ہوتی ہیں.ایک جسم کے اوپر کے حصہ کے لئے اور دوسری نیچے کے حصہ کے لئے.پھر سر بھی ننگا ہوتا ہے اور عرفات وغیرہ میں یہی نظارہ ہوتا ہے.جب لاکھوں آدمی اس شکل میں وہاں جمع ہوتے ہیں توحشر کا نقشہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہم خدا تعالیٰ کے سامنے ہیں اور کفن میں لپٹے ہوئے ابھی قبروں سے نکل کر اس کے سامنے حاضر ہوئے ہیں پھر حج بیت اللہ میں حضرت ابراہیم ؑ حضرت اسمٰعیلؑ حضرت ہاجرہ ؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات زندگی انسان کی آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں اور اس کے اندر ایک نیا ایمان اور عرفان پیدا ہوتا ہے.یوں تو اور قوموں نے بھی اپنے بزرگوں کے واقعات تصویری زبان میں کھینچنے کی کوشش کی ہے جیسے ہندو دسہرہ میں اپنے پُرانے تاریخی واقعات دہراتے ہیں مگر مسلمانوں کے سامنے خدا تعالیٰ نے ان کے آبائو اجداد کے تاریخی واقعات کو ایسی طرز پر رکھا ہے کہ اس سے پرانے واقعات کی یا د بھی تازہ ہو جاتی ہے.اور آئندہ پیش آنے والے حادثہ یعنی قیامت کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے.اسی طرح رمی الجمار کی اصل غرض بھی شیطان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہےاور ان جمار کے نام بھی جمرۃ الدنیا، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ العقبیٰ اس لئے رکھے گئے ہیں کہ انسان اس امر کا اقرار کرے کہ وہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو شیطان سے دور رکھے گا اور عالم برزخ اور عالم عقبیٰ میں بھی ایسی حالت میں جائےگا کہ شیطان کا کوئی اثر اُس کی روح پر نہیں ہو گا.اسی طرح ذبیحہ سے اس طرف توجہ دلائی جاتی
Page 274
ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار رکھے اور جب بھی اس کی طرف سے آواز آئے وہ فوراً اپنا سر قربانی کے لئے جھکا دے اور اس کی راہ میں اپنی جان تک دینے سے بھی دریغ نہ کرے.پھر سات طواف سات سعی اور سات ہی رمی ہیں.اس سات کے عدد میں روحانی مدارج کی تکمیل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.کہ اس کے بھی سات ہی درجے ہیں جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.چنانچہ سورہ مومنون میں ان درجات کی تفصیل دی گئی ہے.اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینا بھی ایک تصویری زبان ہے.بوسہ کے ذریعہ انسان اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس وجود کو جس کو مَیں بوسہ دے رہا ہوں اپنے آپ سے جدارکھنا پسند نہیں کرتا بلکہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے جسم کا ایک حصہ بن جائے.غرض حج ایک عظیم الشان عبادت ہے جو ایک سچے مومن کے لئے ہزاروں برکات اور انوار کا موجب بنتی ہے.مگر افسوس ہے کہ آجکل مسلمان صرف رسمی رنگ میں یہ فریضہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کی برکات سے پوری طرح متمتع نہیں ہوتے.وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اور بعض آدمی ایسے (بھی ہوتے ) ہیں جن کی باتیں (اس)دنیا کی زندگی کے متعلق تجھے (بہت) پسندیدہ معلوم ہوتی يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ١ۙ وَ هُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ۰۰۲۰۵ ہیں اور وہ (بات کرتے وقت) اللہ کو اس (اخلاص) پر جو ان کے دل میں ہے گواہ ٹھہراتے (جاتے) ہیں.حالانکہ وہ (حقیقت میں) سب جھگڑالوؤں سے زیادہ جھگڑالو ہوتے ہیں.حل لغات.اَلَدُّ الْخِصَامِ اَلَدُّ لَدَّ یَلِدُّ سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اَلَدُُّّ کے معنے ہیں شَدِ یْدُ الْخُصُوْ مَۃِ.وہ دشمن جو دشمنی میں بہت بڑھا ہوا ہو.خِصَامٌ یہ مصدر ہے جس کے معنے مجادلہ یعنی جھگڑے کے ہیں(اقرب).تفسیر.فرماتا ہے.دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو تم سمجھتے ہو واہ وا یہ کتنے عقلمند اور سمجھدار ہیں!! یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے سارے علوم پر حاوی ہیں اور ان کی عقل کو کوئی پہنچ نہیں سکتا اور پھر وہ اپنی دینداری کے متعلق اتنا یقین لوگوں کو دلاتے ہیں کہ کہتے ہیں خدا کی قسم! ہمارے دل میں جو نیکیاں بھر ی ہوئی ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا ہم سے مشورہ لیا جائے تو ہم یوں کر دیں وُوں
Page 275
کردیں مگر فرماتا ہے حقیقت کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بدترین دشمن جوتمہارے ہو سکتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ جھگڑا لو اور خطرناک ہوتا ہے وہ ہوتا تمہارے ساتھ ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے اور جب کسی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے تو ساری مجلس پر چھا جاتا ہے اور اپنی دینداری او ر تقویٰ پر قسمیں کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل تو قوم کے لئے گھلا جا رہا ہے.جب دیکھنے والا اسے دیکھتا ہے اورسننے والا اس کی باتیں سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ قطب الاقطاب بیٹھا ہے مگر فرماتا ہے.دنیا میں تمہارے یہودی بھی دشمن ہیں.عیسائی بھی دشمن ہیں او رقومیں بھی دشمن ہیں مگر یہ ان سے بھی بڑا اور خطرناک دشمن ہوتا ہے.بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور تقویٰ کا ایک مجسمہ ہے لیکن معاملہ برعکس ہوتا ہے وہ کوئی دینی نکتے بیان نہیں کرتا بلکہ دنیوی امور کے متعلق ایسی باتیں کرتا ہے جو بظاہر تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر درحقیقت ان کی تہہ میں منافقت کام کر رہی ہوتی ہے.اور پھر ا س کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خداگواہ ہے میرے دل میں تو اخلاص ہی اخلاص ہے اور میں تو محض اپنے دوستوں کی خیر خواہی اور بھلائی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں.فرماتا ہے تم ایسے شخص کی چکنی چپڑی باتوں سے کبھی دھوکا نہ کھائو.اور جب بھی تمہیں کوئی ایسا شخص نظر آئے.فوراً لاحول پڑھ کر اس سے علیٰحدہ ہو جائو اور سمجھ لو کہ تمہارے سامنے ایک شیطان بیٹھا ہے جو قسمیں کھا کھا کر اور اپنی خیر خواہی کا لوگوں کو یقین دلا دلا کر انہیں دھوکا اور فریب دے رہا ہے.وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ اور جب حاکم ہو جاتے ہیں تو فساد (پیدا) کرنے اور کھیتی (باڑی) اور مخلوق کو ہلاک کرنے کی غرض سے (سارے) وَ النَّسْلَ١ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۰۰۲۰۶ ملک میں دوڑتے پھرتے ہیں.حالانکہ اللہ (تعالیٰ) فساد کو پسند نہیں کرتا.حل لغات.تَوَلّٰی وَلِیَ سے باب تفعُّل ہے اور اَلتَّوَلِّیْ کے معنے ہیں اَلْاِنْصِرَافُ بِالْبَدْنِ اَوِالْقَوْلِ.بدن کے ساتھ پھر جانا یعنی پیٹھ پھیر لینا.مرتد ہو جانا یا (۲)اپنی بات سے پھر جانا(۳) حاکم اور والی بن جانا.(لسان العرب) اَلْحَرْثُ کے معنے ہیں مَایَسْتَنْبُتُ بِالْبَذْرِ وَالنَّوٰی وَالْغَرْسِ.یعنی جو چیز بیج گٹھلی یا پودے سے اُگائی
Page 276
جائے.(اقرب) نَسْل کے معنے ہیں (۱) عقب یعنی اولاد بیٹے بیٹیاں (۲) مخلوق (۳) اگلی نسل یعنی صرف بیٹوں تک ہی نہیں بلکہ دس دس بیس بیس پشتوں تک جو اولاد چلتی ہے اُسے بھی نسل ہی کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.فرمایا ایسے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں بادشاہت مل جاتی ہے یعنی وہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ طاقتوں سے کام لے کر حکومت پر قابض ہو جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ رعایا اور ملک کی خدمت کریں بجائے اس کے کہ لوگوں کے دلوں میں سکینت اور اطمینان پیدا کریں وہ ایسی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دیتے ہیں جن سے قومیں قوموں سے.قبیلے قبیلوں سے اور ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں اور ملک میں طوائف الملوکی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے.اسی طرح وہ ایسے طریق اختیار کرتے ہیں جن سے ملک کی تمدنی اور اخلاقی حالت تباہ ہو جاتی ہے اور آئندہ نسلیں بیکار ہو جاتی ہیں.حرث کے لغوی معنے تو کھیتی کے ہیں مگر یہاں حرث کا لفظ استعارۃً وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ جتنے ذرائع ملک کی تمدنی حالت کو بہت بنانے والے ہوتے ہیں ان ذرائع کو اختیار کرنے کی بجائے وہ ایسے قوانین بناتے ہیں جن سے تمدن تباہ ہو.اقتصاد برباد ہو.مالی حالت میں ترقی نہ ہو.اس طرح وہ نسلِ انسانی کی ترقی پر تبر رکھ دیتے ہیں.اور ایسے قوانین بناتے ہیں جن سے آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں اپنی طاقتوں کو کھو بیٹھتی ہیں اور ایسی تعلیمات جن کو سیکھ کر وہ ترقی کر سکتی ہیں ان سے محروم رہ جاتی ہیں.پھر فرماتا ہے وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ ا للہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتا.اس لئے ایسے بادشاہ اور حکمران خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مغضوب ہیں اور وہ ان کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک وہی بادشاہ صحیح معنوں میں بادشاہ کہلا سکتا ہے جو لوگوں کے لئے ہر قسم کا امن مہیّا کرے.ان کی اقتصادی حالت کو درست کرے اور ان کی جانوں کی حفاظت کرے.کیا بلحاظ صحت کا خیال رکھنے کے اور کیا بلحاظ اس کے کہ وہ غیر ضروری جنگیں نہ کرے اور اپنے ملک کے افراد کو بلاوجہ مرنے نہ دے.گویا ہر قسم کے امن اور جان و مال کی حفاظت کی ذمہ واری اسلام کے نزدیک حکومت پر عاید ہوتی ہے.اور وہ اس امر کی پابند ہے کہ ملک کی ترقی اور رعایا کی بہبودی کا ہمیشہ خیال رکھے.
Page 277
وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ اور جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو (اپنی) عزت (کی پچ) انہیں گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے پس اس جَهَنَّمُ١ؕ وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ۰۰۲۰۷ ( قسم کے لوگوں)کے لئے جہنم کافی ہے اوروہ یقیناً بہت بُرا ٹھکانہ ہے.حل لغات.اِتَّق وَقٰی یَقِیْ سے باب افتعال کا امر کا صیغہ ہے اس کے اصل معنے یہ ہیں کہ انسان اس چیز سے جو سامنے سے آرہی ہو بچنے کے لئے ہٹ جائے مگر یہ معنے اس جگہ چسپاں نہیں ہوتے کیونکہ انسان خدا تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا.خواہ وہ کسی جگہ چلا جائے بہر حال دوسرے معنے ہی لینے پڑیں گے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت کا ذریعہ بنا لے (لسان العرب).اَخَذَ تْہُ اَلْاَخْذُ کے معنے ہیں حَوْزُ الشَّیْءِ وَتَحْصِیْلُہٗ.....وَتَارَۃً بِالْقَھْرِ.کسی چیز کو زبردستی لے لینا یا حاصل کرنا یا پکڑ لینا (اقرب) اور اَخَذَ تْہُ بِکَذَا کے معنے ہیں حَمَلَتْہُ عَلٰی کَذَا.اُسے کسی کام پر اکسا دیا یا اُس کی ترغیب دی.(اقرب) اَلْعِزَّۃُ وَرُبَمَا اسْتُعِیْرَتِ الْعِزَّۃُ لِلْحَمِیَّۃِ و الْاَنْفَۃِ الْمَذْمُوْ مَۃِ.وَمِنْہُ فِی الْقُرٓاٰنِ وَاِذَا قِیْلَ لَہُ اتَّقِ اللّٰہَ اَخَذَتْہُ الْعِزَّۃُ بَا لْاِثْمِ (اقرب) یعنی بعض اوقات عزۃ کا لفظ بطور استعارہ جھوٹی غیرت اور پچ کےلئے بھی استعمال ہوتا ہے.پس اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ کے معنے یہ ہوئے کہ جھوٹی قومی غیرت نے اُسے گناہ کی خاطر گھیر لیا یا اُسے گناہ پر آمادہ کر دیا.جَھَنَّمُ دَارُ الْعِقَابِ بَعْدَ الْمَوْتِ.یعنی جہنم موت کے بعد سزا کی جگہ کا نام ہے (اقرب) جہنم کے لئے قرآن کریم میں اور بھی کئی لفظ آتے ہیں.جیسے جَحِیْمٌ، سَعِیْرٌ، سَقَرْ، لظٰی وغیرہ.مِھَادٌ وہ جگہ جہاں انسان تھک کر آرام کرے جیسے بستر وغیرہ.تفسیر.فرماتا ہے جب اُسے کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو.تم تو دو کوڑی کے بھی آدمی نہیں تھے تمہیں تو جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کی و جہ سے ملا ہے.تو اَخَذَتْہُ الْعِزَّۃُ بِالْاِثْمِ اُسے اپنی جھوٹی عزت کی پچ گناہوں پر اور زیادہ دلیر کرتی ہے.اس کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں یہ بھی کہ اس کے پہلے گناہوں اور
Page 278
شامت اعمال کی وجہ سے ہتک عزت کا جنون اس کے سرپر سوار ہو جاتا ہے اور اسے ہدایت سے اور زیادہ دور پھینک دیتا ہے.اور یہ بھی کہ اپنی عزت کی پچ اُسے گناہوں کے لئے پکڑلیتی ہے یعنی اس سے اور زیادہ گناہوں کا ارتکاب شروع کرا دیتی ہے.فرماتا ہے یہاں ممکن ہے تم لوگوں کو فریب دے لو لیکن آخر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے.وَ لَبِئْسَ الْمِهَادُ.اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے.جہنم بے شک اگلے جہان میں ہے لیکن ایک جہنم ایسے انسانوں کے لئے اس جہان میں بھی پیدا کر دیا جاتا ہے جب شریف انسان مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں تو انہیں ایسا جواب مل جاتا ہے کہ یہی دنیا ان کے لئے جہنم بن جاتی ہے افسوس ہے کہ دنیا میںبہت سے لوگ صرف اس لئے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے کہ جب انہیں ان کی غلطی بتائی جائے او رکہا جائے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو.تو اپنی ہتک عزت کے خیال سے وہ دیوانہ ہو کر بجائے نصیحت سے فائدہ اٹھانے کے ناصح کا مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ جس کسی میں کوئی غلطی یا نقص دیکھے بازار میں کھڑے ہو کر اُسے تنبیہہ کرنا شروع کردے.سمجھانا ہمیشہ علیحدگی میں چاہیے.اور سمجھانے والے کو اپنی حیثیت اور قابلیت بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ جس شخص کو سمجھانا چاہتا ہے اسے سمجھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں.تاکہ اس کا اُلٹا نتیجہ نہ نکلے غرض جہاں غلطی کرنے والوں کو برداشت کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور سمجھانے والے کی بات کو ٹھنڈے دل سے سنُنا چاہیے.وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ سمجھانے والا احتیاط سے کام لے.یہ نہ ہو کہ وہ جس کو چاہے لوگوں میں ذلیل کرنا شروع کر دے.اس مثال کو حج کے ساتھ اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ حج کی بڑی غرض قومی تفرقوں کو مٹا کر اتفاق و اتحاد اور محبت و یگا نگت کے تعلقات کو بڑھانا ہے.مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں لڑتے جھگڑتے اور فساد پیدا کرتے رہتے ہیں.انہیں متوجہ کیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ ساری دنیا کو ایک مرکز پر جمع کرنا چاہتا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اتفاق و اتحاد قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے کینے اور بغض چھوڑدیں.درحقیقت صحیح معنوں میں حج کرنے والا صرف وہی شخص کہلا سکتا ہے جو اس قسم کے فتنہ و فساد سے مجتنب رہے.لیکن جو شخص فساد کرتا اور بنی نوع انسان کو دکھ پہنچاتا ہے وہ اپنے عمل سے اس وحدت اور مرکزیت کو نقصان پہنچاتا ہے جس کو قائم کرنے کےلئے اسلام نے حج بیت اللہ کا حکم دیا ہے.
Page 279
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ١ؕ اور بعض آدمی ایسے (بھی) ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کو (ہی) بیچ ڈالتے ہیں.وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ۰۰۲۰۸ اور اللہ (اپنے ایسے مخلص ) بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے.حل لغات.یَشْریْ شَرٰی سے مضارع کا صیغہ ہے اور شَرٰی کے معنے خریدنے اور بیچنے دونوں کے ہوتے ہیں.(اقرب) رَءُ وْفٌ رَءُ وفٌ فَعُوْلٌ کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے.رَءُ وْفٌ رَأْ فَۃٌ سے ہے اور رأفت کے معنے تکلیف کو دیکھ کر اس کے دور کرنے کی طرف توجہ کرنے کے ہیں.رأفت اور رحمت دونوں ہم معنے لفظ ہیں مگر رحمت وسیع ہے اور رأفت قدرے محدود ہے.اس کے معنے یہ ہیں کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اُسے چھڑانا.پس رئووف کے معنے ہوئے تکلیف میں دیکھ کر چھڑانے والا.رحمت دُکھ و سکھ دونوں کے لئے ہوتی ہے.مگر رأفت ہمیشہ دکھ پر ہی ہوتی ہے گویا رحمت عام ہے اور رأفت خاص.تفسیر.اس مثال میں بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اُسے بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے اپنی جان کو بھی قربان کرنے پر تیار رہتے ہوں وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کےلئے کب کوئی قدم اُٹھا سکتے ہیں؟ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہیں بھی آخر الذکر گروہ کا سا طریق اختیار کرنا چاہیے اور نہ صرف فتنہ و فساد سے مجتنب رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینا چاہیے.وَ اللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کر نے والا ہے.اس کی شفقت کا تقاضا ہے کہ تم بھی فتنہ و فساد سے بچو.اور اپنی زندگیوں کو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے کاموں میں صرف کرو تاکہ تم بھی رءوف بالعباد خدا کے مظہر بن جائو.
Page 280
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً١۪ وَّ لَا اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تم سب کے سب فرمانبرداری (کے دائرہ) میں آجاؤ.اور تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ١ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۰۰۲۰۹ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو.وہ یقیناً تمہارا کھلا (کھلا) دشمن ہے.حلّ لُغات.اَلسِّلْمُ کے معنے ہیں اَلصُّلحُ.اَلسَّلَامُ وَالْاِسْلَامُ (اقرب) یعنی (۱) صلح (۲) امن کو قائم کرنا (۳)اسلام.کَآفَّۃً کَفٌّ کے معنے ہیں جمع کرنا.روکنا.پس کَآفَّۃٌ کے معنے جمع کرنے والے یاروکنے والے کے ہیں.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے.اے مومنو! تم سارے کے سارے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائو اور اس کی اطاعت کا جُوا اپنی گردنوں پر کامل طور پر رکھ لو.یا اے مسلمانو! تم اطاعت اور فرمانبرداری کی ساری راہیں اختیار کرو اور کوئی بھی حکم ترک نہ کرو.اس آیت میں کَآفَّۃً اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کا بھی حال ہو سکتا ہے اور اَلسِّلْمِ ِ کا بھی.پہلی صورت میں اس کے یہ معنے ہیں کہ تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائو یعنی تمہارا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اطاعت اور فرمانبرداری کے مقام پر کھڑا نہ ہو.یا جس میں بغاوت اور نشوز کے آثار پائے جاتے ہوں.دوسری صورت میں اس کے یہ معنے ہیں کہ تم پورے کا پوراا سلام قبول کرو.یعنی اس کا کوئی حکم ایسا نہ ہو جس پر تمہارا عمل نہ ہو.یہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر مومن سے چاہتا ہے کہ انسان اپنی تمام آرزوئوں تمام خواہشوں اور تمام امنگوں کو خدا تعالیٰ کے لئے قربان کر دے اور ایسا نہ کرے کہ جو اپنی مرضی ہو وہ تو کر لے اور جو نہ ہو وہ نہ کرے.یعنی اگر شریعت اس کو حق دلاتی ہو تو کہے میں شریعت پر چلتا ہوں اور اسی کے ماتحت فیصلہ ہونا چاہیے لیکن اگر شریعت اس سے کچھ دلوائے اور ملکی قانون نہ دلوائے تو کہے کہ ملکی قانون کی رو سے فیصلہ ہونا چاہیے.یہ طریق حقیقی ایمان کے بالکل منافی ہے.چونکہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ مسلمانوں میں بعض ایسے کمزور لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو قومی ترقی اور رفاہیت کے دور میں فتنہ و فساد پر اُتر آتے ہیں.اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری پہلی حالت کیا تھی او رپھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں کیا کچھ عطا کر دیا.اس لئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت فرماتا ہے کہ بے شک تم مومن کہلاتے ہو مگر تمہیںیاد رکھنا چاہیے کہ صرف مونہہ سے اپنے آپ کو مومن کہنا تمہیں نجات کا مستحق نہیں بنا سکتا.تم اگر
Page 281
نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ اوّل ہر قسم کی منافقت اور بے ایمانی کو اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرو.اور قوم کے ہر فرد کو ایمان اور اطاعت کی مضبوط چٹان پر قائم کر دو.دوم صرف چندا حکام پر عمل کر کے خوش نہ ہو جائو.بلکہ خدا تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل بجالائو.اور صفاتِ الٰہیہ کا کا مل مظہر بننے کی کوشش کرو.پھر فرماتا ہے وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ١ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.تم شیطان کے پیچھے نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.اس آیت میں خطوات کا لفظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے کہ شیطان ہمیشہ قدم بقدم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے.وہ کبھی یکدم کسی انسان کو بڑے گناہ کی تحریک نہیں کرتا بلکہ اسے بدی کی طرف صرف ایک قدم اٹھانےکی ترغیب دیتا ہے اور جب وہ ایک قدم اُٹھا لیتا ہے تو پھر دوسرا قدم اُٹھانےکی تحریک کرتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ اور قدم بقدم اسے بڑے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے پس فرماتا ہے ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تمہاراصرف چند احکام پر عمل کر کے خوش ہوجانا اور باقی احکام کو نظر انداز کر کے سمجھ لینا کہ تم پکے مسلمان ہو ایک شیطانی وسوسہ ہے.اگر تم اسی طرح احکام الٰہیہ کو نظر انداز کرتے رہے تو رفتہ رفتہ جن احکام پر تمہارا اب عمل ہے ان احکام پر بھی تمہار ا عمل جاتا رہےگا.پس اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہو.اور شیطانی وساوس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو.فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس کھلے(کھلے) نشان آئے ڈگمگاگئے تو جان لو کہ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۰۰۲۱۰ اللہ یقیناًغالب (اور )حکمت والا ہے.تفسیر.فرماتا ہے اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے اور طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد بنی نوع انسان کی خدمت کرنے کی بجائے ان پر ظلم کرنا شروع کردوگے.اور انہیں مالی اور جانی نقصانات پہنچائو گے تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے سر پر ایک غالب خدا موجود ہے جو تمہیں سزا دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور تم سے تمہارا اقتدار بھی چھین سکتا ہے.پس خدا تعالیٰ سے ڈرو جو ایکدم میں تمہیں بادشاہ سے گدا اورامیر سے فقیر بنا سکتا ہے اور تمہاری عزّت کو ذلّت سے بدل سکتا ہےمگر ساتھ ہی حکیم کہہ کر بتایا کہ اس کا کوئی فعل ظالمانہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہر
Page 282
کام کے پیچھے بڑی بڑی حکمتیں کام کر رہی ہوتی ہیں.پس اس کی سزا بھی ظالمانہ نہیں ہوتی بلکہ انسانی اصلاح کے لئے ہوتی ہے.اگر لوگ اپنی درندگی چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرلیں.اور بنی نوع انسان کی خدمت اپنا شعار بنا لیں اور سچائی اور راستی اور دیانت اور امانت کو اختیار کر لیں اور ہر قسم کا کھوٹ اپنے دلوں میںسے نکال دیں اور پاک باطن اور نیک دل اور بااخلاق اور خدا ترس بن جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا اور ان کی تضرعات کو سنتا اور ان کی ناکامیوں اور ذلتوں کو کامیابیوں اور عزّتوں میں بدل دیتا ہے.هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وہ (لوگ )اس کے سوا کس (بات) کا انتظار کر رہے ہیںکہ اللہ (تعالیٰ) ان کے پاس بادلوں کےسایوں میں آئے وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ وَ قُضِيَ الْاَمْرُ١ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُؒ۰۰۲۱۱ اور فرشتے بھی (آئیں )اور بات کا فیصلہ کر دیا جائے.اور تمام امور اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں.تفسیر.اس میں بتایا کہ یہ کفار جو مسلمانوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور منافق جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں اور اسلام کی تباہی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں.یہ لوگ بظاہر تو اس بات کے منتظر ہیں کہ کب وہ دن آئے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے اور خدائے واحد کی حکومت پر شیطانی طاقتیں غلبہ حاصل کر لیں لیکن درحقیقت اپنے عمل سے وہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس بادلوں کے سایوں میں آئے.یعنی اپنی مخفی تدبیر سے ان کی ہلاکت اور بربادی کے سامان پیدا کر دے.وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ آسمان سے اس کے فرشتے نازل ہوں جو انہیں کچل کر رکھ دیں.وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ کوئی ایسا نشان ظاہر ہو جس کے نتیجہ میں یہ روز روز کے جھگڑے مٹ جائیں اور خدا تعالیٰ کا آخری فیصلہ ایک چمکتے ہوئے نشان کی صورت میں سب کو نظر آجائے.اور آخر ایک دن ایسا ہی ہوگا.خدا ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گا اور ان کی ہلاکت کی ساعت ان کے سروں پر منڈلانے لگے گی.چنانچہ جنگِ بدر میں خدا تعالیٰ نے بادلوں میں سے ہی اپنا چہرہ ظاہر کیا.یعنی ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ بارش ہوئی جس سے کفار کو شدید نقصان اور مومنوں کو جنگی لحاظ سے عظیم الشان فائدہ پہنچا اور پھر مومنوں کی مدد اور کفار پر رُعب طاری کرنے کے لئے ملائکہ بھی دلوں پر نازل ہوئے.بلکہ جنگِ بدر میں کئی کفار نے ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا(الانفال:۱۰.السیرۃ النبویۃ لابن ہشام ،واقعہ بدر).اور قُضِیَ الْاَمْرُ کے ماتحت
Page 283
عرب کے سردار چُن چُن کر مارے گئے.یہاں تک کہ وہ بھی جسے وہ سیدالوادی کہتے تھے دو انصاری لڑکوں کے ہاتھ سے مارا گیا (بخاری کتاب المغازی باب قتل ابی جھل).اور مکہ میں ایسا کہرام مچا کہ کوئی گھر نہ تھا جس میں ماتم نہ پڑاہو.اور گو یہود پراس کا براہ راست کوئی اثر نہیں پڑا مگر اس جنگ کے نتیجہ میں ہی ان کی شرارتیں ظاہر ہوئیں.اور آخر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے.غرض ان کا منہ مانگا نشان انہیں مل گیا اور ان کی شوکت کی جڑھ کاٹ کر رکھ دی گئی اور پھر یہی سلوک بعد میں پیدا ہونے والے دشمنوں سے بھی ہوتا رہا اور خدا تعالیٰ انہیں اپنی قہری تجلی کے جلوے بار بار دکھاتا رہا یہاں تک کہ اسلام دنیا پر غالب آگیا.سَلْ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۭ بَيِّنَةٍ١ؕ وَ (ذرا) بنی اسرائیل سے پوچھو (تو) کہ ہم نے انہیں کتنے کھلے کھلے نشان دئیے تھے اور جو شخص اللہ کی (کسی) مَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اسے حاصل ہو جائے (اور وہ اس حقیقت کو سمجھ چکا ہو ) بدل ڈالے تو (وہ یاد رکھےکہ ) اللہ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۰۰۲۱۲ (بھی )سخت سزا دینے والا ہے.تفسیر.میں ترتیب مضمون کو بیان کرتے ہوئے اوپر بتا چکا ہوں کہ اس جگہ یہود مخاطب ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیشگوئی پر بحث ہو رہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعثت کے متعلق تھی.اور آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق ثابت کیا جارہا ہے.چنانچہ اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں فتح مکہ کی پیشگوئی کی.یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جبکہ مکہ پر کفار کاغلبہ اور حکومت تھی اور مسلمان مدینہ میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے.اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام کے ذریعے بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم مکہ فتح کر لو گے اور تمہارے لئے حج بیت اللہ کے راستے بالکل کھل جائیں گے.پھر اسی ضمن میں صلح حدیبیہ کی بھی پیشگوئی کی کیونکہ بتایا کہ اگر تمہیں عمرہ سے روکا جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے.گویا پہلے سے پیشگوئی کر دی کہ تمہیں ایک زمانہ میں عمرہ کرنے سے بھی روکا جائےگا.
Page 284
اسی طرح مَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں یہ اشارہ مخفی تھا کہ مکہ ایک دن تمہارے لئے گھر کے طور پر بننے والا ہے.غرض ان آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ مکہ کے دروازے تمہارے لئے کھلنے والے ہیں.اور تم اس میں امن سے داخل ہو گے.چنانچہ فتح مکہ سے پہلے ہی فرما دیا کہفَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ جب تم امن میں آجائو تو ایسا کرو.اب ان پیشگوئیوں کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم ان سے پوچھو کہ ہم نے انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی صداقت کے کس قدر کھلے نشانات دکھائے ہیں اور یہ جو ہم نے فتح مکہ کی پیشگوئی کی ہے یہ بھی ایک زبردست نشان ہے جس سے ثابت ہو جائےگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں.پس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ناقدری کرتے ہوئے اسے مٹانے کے درپے ہیں.انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دےگا.چنانچہ فتح مکہ کے ساتھ ہی یہود کی بھی انتہائی ذلت ہوئی اور وہ بھی تباہ ہوتے چلے گئے.اس آیت کا ایک یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہود کو پہلے بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں جن کی انہوں نے ناشکری کی مثلاً سب سے بڑی نعمت تو ان پر یہی نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لئے متواتر انبیاء ان میں مبعوث فرمائے لیکن یہود نے ہمیشہ ان کی تکذیب کی اور ان کی مخالفت کو اپنا شعار بنائے رکھا.یہاں تک کہ بعض انبیاء کو انہوں نے جان سے بھی مارڈالا.یہ خدا تعالیٰ کی نعمت کی ایک عظیم الشان ناشکری تھی جو ان سے ظاہر ہوئی.اسی طرح عیسائیوں نے جو یہود کی ایک شاخ ہیں اس قدر ناشکری کی کہ شریعت کو لعنت قرار دے دیا.غرض یہود کی ان متواتر سرکشیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتِ نبوت ان سے واپس لے لی کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا الٰہی سنّت کے مطابق وہ نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں اور اسے رنج و غم اور حسرت ویاس کے لمبے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے.زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُوْنَ مِنَ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں دنیوی زندگی خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے.اور وہ ان لوگوں سے جو ایمان الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا١ۘ وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ١ؕ لائے ہیں ٹھٹھا کرتے ہیں.اور (اس کے بالمقابل) جن لوگوں نے تقویٰ اختیار کیا ہے وہ (ان) کفار پر قیامت
Page 285
وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۰۰۲۱۳ کے دن غالب ہو ں گے.اور اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے بے حساب دیتا ہے.تفسیر.فرمایا یہ لوگ ابھی اس پیشگوئی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے.کیونکہ دنیا اپنی تمام دلفریبیوں اور رعنائیوں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہے اور طاقت اور دولت کے نشہ نے ان کی نگاہوں کو ایسا خیرہ کر رکھا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں سے کہاں شکست کھا سکتے ہیں بلکہ وہ ان پیشگوئیوں پر مسلمانوں سے تمسخر کرتے اور ان کا مضحکہ اُڑاتے ہیں اور انہیں طعنے دیتے ہیں کہ ہمیں تو نقدمل رہا ہے.تمہارا انعام کہاں ہے؟ مگر ایک دن ان کو معلوم ہو جائے گاکہ ہم کس طرح مسلمان کو غلبہ عطا کرتے اور کفار کو نیچا دکھاتے ہیں.چنانچہ فرمایا وَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِِ جب قیامت کا دن آئےگا تو متقی لوگ ان کفار پر غالب ہوںگے اس میں کوئی شبہ نہیں کہفَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِِ کا نظارہ اس قیامت کے دن بھی ہو گا جو مرنے کے بعد آنے والا ہے جب کہ کفار دوزخ میں جائیں گے اور مومن جنت میں اور وہ ہمیشہ کے لئے فوق ہو جائیں گے کیونکہ آخرت میں مقابلہ تو ہے نہیں کہ دوزخی جنتیوں پر کسی وقت فوقیت لے جاسکیں.مگر اس قیامت کے دن سے لوگ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اسے حجت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور اس آیت میں اس غلبہ کو بطور دلیل صداقت پیش کیا گیا ہے.پس اس آیت میں یومِ قیامت سے مراد وہی دن ہے جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اور کفار کو شکست جس دن دنیا نے یہ عجیب نظارہ دیکھا کہ وہ جو اکیلا اور بے یارومددگار تھا اور قوم کے ظلموں کا نشانہ بنا ہوا تھا وہ تو حاکم ہو گیا اور جو ملک کے بادشاہ اور حکمران تھے محکوم اور ذلیل ہو گئے.وَالَّذِیْنَ اتَّقَوْا کے الفاظ میں مومنوں کو بھی اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کفار پر حقیقی غلبہ حاصل کرنے کے لئے سب سے بڑی چیز جس کی تمہیں ضرورت ہے وہ تقویٰ ہے بیشک ایمان بھی ایک قیمتی دولت ہے لیکن اگر اس ایمان کے مطابق عمل نہیں تو وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رکھتا.وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ میں بغیر حساب کے الفاظ کفار کے لئے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے ہیں.اور جب کوئی چیز بے حساب ملے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدلہ سے بہت زیادہ ہے.حساب کر کے تو جتنا کسی کا حق بنتا ہے اتنا ہی دیا جاتا ہے مگر بغیر حساب کے اسی صورت میں دیا جاتا ہے جب حق سےزیادہ دیا جائے.پس ان الفاظ میں یہ اشارہ مخفی ہے کہ مومنوں کو ان کے بدلہ سے بہت بڑھ چڑھ کر انعام ملےگا.دوسرے اس میں کفار کو بتایا
Page 286
کہ تم کو جو کچھ ملا ہے اس کے متعلق تو تم سے پوچھا جائے گا کہ کس کس طرح خرچ کیا ہے؟ لیکن ان کو اس طرح ملے گا کہ ان سے حساب بھی نہیں لیا جائےگا.گویا تم کو تو ملازموں کی طرح ملا ہے اور تم اس میں خیانت کر کے سزا کے موردبنتے ہو.لیکن ان کو ہدیہ کے طور پر ملےگا.اور اس میں تصرف کا ان کو اختیار کامل ہو گا.دراصل سلوک دو قسم کا ہوتا ہے ایک دوستانہ اور دوسرا ملازمانہ.چونکہ دوستی میں غیریت باقی نہیں رہتی اس لئے فرمایا کہ ہم مومنوں کو بغیر حساب دیںگے اور ان سے ایسا سلوک کریں گے جو ایک دوست دوست سے کرتا ہے.چنانچہ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت میں سے ستّرہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوںگے (بخاری کتاب الرقاق باب یدخل الجنة سبعون الفا بغیر حساب) لیکن جس کے ساتھ غیریت کا معاملہ ہو اس سے سختی کے ساتھ حساب لیا جاتا ہے اور حساب ہی کے مطابق اسے معاوضہ دیا جاتا ہے.اسی لئے قرآن کریم میں کفار کے متعلق یہ الفاظ کہیں استعمال نہیں ہوئے کہ انہیں بغیر حساب دیا جائےگا.بلکہ ان کے متعلق جہاں بھی آیا ہے یہی آیا ہے کہ وَاللّٰہُ سَرِیْعُ الْحِسَابِ.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ یعنی وہ شخص جس کا سختی سے حساب لیا گیا وہ تباہ ہوا.حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا قرآن میں یہ نہیں آتا کہ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرً ا (الانشقاق:۹) اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کا بھی حساب ہو گا.آپ نے فرمایا حساب سے مراد یہ ہے کہ پوری طرح حساب لیا جائے ورنہ مومن کا حساب تو محض سرسری ہو گا (بخاری کتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب) پس مومنوں کو جو کچھ ملے گا بغیر حساب کے ہی ملے گا.اسی طرح بغیر حساب کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا انعام ملے گا.اور چونکہ یہ آیت اس دنیا کے غلبہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس لئے وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قربانیوں سے بہت زیادہ اجر عطا فرمائے گا.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی غلامی میں اس دنیا میں جو کچھ ملا وہ بے حساب ہی ملا.بے شک ان کی قربانیوں کی چمک بھی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی ہے.مگر اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دینی اور دنیوی رنگ میں غیر معمولی اجر عطا فرمایا وہ ان کی قربانیوں سے بہت زیادہ تھا.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو مادی رنگ میں انہیں تختِ شاہی پر بٹھا دیا اور دوسری طرف روحانی رنگ میں انہیں ایسی برکات سے نوازا کہ رَضِیَ عَنْھُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ (التوبة:۱۰۰) کا دائمی سرٹیفکیٹ انہیں حاصل ہو گیا.
Page 287
وجہ سے کہ مسلمانوں کو بھی جنّت کا حقدار بنا دیا گیا ہے.گویا ایک تو بغاوت اور دوسرے حسد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا.اپنا ذاتی فائدہ مدنظر نہ رکھا اور سودا فسخ کر دیا.دوم.اِشْتَریٰ کے معنے اگربیچنے کے لئے جائیں تو کسی چیز کے بدلے میں اپنی جانوں کو بیچنے کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ انسان اُس میں منہمک ہو جائے.اس صورت میںبِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ کے یہ معنے ہونگے.کہ وہ چیز جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے.بہت بُری ہے.یعنی کفر.کفر کے لئے اپنے آپ کو فروخت کردینا درحقیقت ایک محاورہ ہے بدی میں مبتلا ہو جانے کا.اردو زبان میں بھی کہتے ہیں.کہ تم فلاں بات میں ہی لگ گئے ہو.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ کفر میں ہی منہمک ہو چکے ہیں اور اِن کی کفر میں ترقی کی بڑی وجہ یہ حسد ہے کہ نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی.مسلمانوں کو کیوں مل گئی ہے.غرض یہاں اِشْتَریٰ کے دونوں معنے چسپاں ہو سکتے ہیں خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی.فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍمیں بتایا کہ یہود خدا تعالیٰ کے متواتر غضب کو لے کر اس طرح بن گئے کہ گویا خدا تعالیٰ کا غضب انہیں کے لئے مخصوص کیا گیا ہے.چنانچہ ایک دفعہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ! سورۃ فاتحہ میں جو مغضوب اور ضالین کا ذکر آتا ہے اس میں مغضوب سے کون لوگ مراد ہیں.تو آپؐ نے فرمایا.یہود.(ترمذی ابواب التفسیروفتح البیان زیر آیت ۷ سورۃ الفاتحہ) اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ متواتر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا مقابلہ کرتے رہے اور غضب الٰہی کے مورد بن گئے.بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ کے الفاظ اس لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہود حضرت مسیحؑ کا انکار کر کے خدا تعالیٰ کے غضب کا مورد بنے تھے اور دوسری دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کا انکار کر کے وہ اُس کے غضب کا مورد بنے گویا دوہرے طور پر وہ غضبِ الٰہی کامورد بن گئے.وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ میں بتایا کہ حسد کرنے والے آخر میں ضرور رُسوا ہوتے ہیں.اگر دیانتدار ی سے کسی مذہب کی مخالفت ہو تو وہ ایک علیحدہ امر ہے لیکن یہود کو اپنی کتاب کی پیشگوئیاں دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صداقت کا علم ہو چکا تھا.مگر اس کے باوجود وہ آپ کا انکار کرتے رہے.اور جو شخص کسی صداقت کا عمداً انکار کرتا ہے وہ یقینا رُسوا ہو تا ہے بلکہ اگر بعد میں وہ مان بھی لے تب بھی لوگ اسے رُسوا کرتے ہیں کہ اِس نے انکار کرکے مان لیا.
Page 288
مُّسْتَقِيْمٍ۰۰۲۱۴ اللہ جسے پسندکرتا ہے سیدھی راہ پر چلادیتا ہے.تفسیر.اس آیت کے متعلق بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا یہ کہ لوگ ایک اُمت تھے یعنی سب نیک تھے پھر نبی آئے اور اختلاف ہو گیا.یا یہ کہ لوگ بدتھے اورپھر نبی آئے.میرے نزدیک اس کے یہی معنے ہیں کہ لوگ بد تھے اور نبی آئے.اس کی دلیل قرآن کریم سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نبی لوگوں کی خرابی پر ہی بھیجتا ہے خود اس آیت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ بد تھے.کیونکہ فرمایا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ.نبی بشارتیں اور انذار لے کر آئے اور انذار کا ساتھ ہونا بتاتا ہے کہ خدا سے دور لوگ موجود تھے.دوسرا ثبوت اسی آیت سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ.وہ نبی اس لئے آئے کہ جس بات میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اس میں فیصلہ کریں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسائل کے متعلق اختلاف موجو دتھا پس یہ بھی دلیل ہے کہ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً سے یہ مراد نہیں کہ لوگ نیک تھے.اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً کیوں کہا؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اَلْکُفْرُمِلَّۃٌ وَاحِدَۃٌ کُفر بھی ایک ہی ملّت ہے.یعنی اصل الاصول کفر کا یہی ہے کہ خدا سے لوگوں کو دور کیا جائے جس طرح اسلام بھی ملّتِ واحدہ ہے.یعنی سب اسلامی اُمتیں ایک ہیں.کیونکہ ان کے اصول ایک ہیں.گو تفصیلِ شرائع میں اختلاف ہو.پس ملت ِواحدہ کہنے سے مراد ان کا اتفاق یا باہمی محبت بتانا مدِّنظر نہیں بلکہ یہ مدِّ نظر ہے کہ سب کافر ہی کافر تھے نیک لوگ ان میں نہ تھے کیونکہ کفر کے مقابلہ میں دوسری جماعت در حقیقت مومنوں کی ہی ہوتی ہے.کافر آپس میں خواہ کتنے ہی مختلف الخیال ہوں پھر بھی اصل غرض جو خدا کا قرب پانا ہے اس کے متعلق سب کا ایک ہی رویہ ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے دائرہ میں ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی خدا سے لوگوں کو دور کردینا.یا یہ کہ کَانَ کے معنے ’’تھے‘‘ کے نہیں بلکہ ’’ہیں ‘‘ کے ہیں.اور اس کا یہ مطلب ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اُمَّۃٌ وَاحِدَۃٌ بنایا ہے.یعنی دوسرے حیوانات بھی اُمت ہیں مگر امت ِ واحدہ نہیں ہیں.انسان مدنی الطبع ہے اور اس کو آپس میں مل کر رہنا پڑتا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ اختلاف اور شقاق پیدا ہونا ہے.بڑی نعمت کےساتھ بڑے خطرات بھی ہوتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کی بدیاںبھی انسان اخذ کر تا ہے.جب تمدن کے یہ نقائص بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے جو اختلاف کو دور کر دیں اور ملنے جلنے کی وجہ سے جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور ضد کی وجہ
Page 289
سے لوگ اپنااپنا دین بنا بیٹھے ہیں اس کی وہ اصلاح کریں.اگر کہا جائے کہ یہ معنے ہوتے تو چاہیے تھا کہ کَانَ النَّاسُ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً فَتَشَاجَرُوْ وَاخْتَلَفُوْا فَبَعَثَ اللّٰہُ النَّبِیّٖنَ ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ فَا نے اس امر پر دلالت کر دی ہے کہ پچھلی بات پہلی بات کے نتیجہ میں ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اُمَّةً وَّاحِدَةً ہونے کا نتیجہ نبیوں کی بعثت نہیں ہے.اس لئے یہاں لازماً مقدر تسلیم کرنا پڑےگا اور فِیْمَا اخْتَلَفُوْافِیْہِ اس مقدر کی طرف اشارہ کر رہا ہے.وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اَلْکُتُب نہیں کہا بلکہ اَلْکِتٰبکہا ہے جس میں جنس کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہر نبی کو کو ئی نہ کوئی کتاب ضرور دی جاتی ہے خواہ نئی ہو یا پرانی.یہ نہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ کتاب ملے.بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نبی کو الگ الگ کتاب دی جاتی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے.اور تاریخی طور پر اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا بلکہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی اس مضمون کی تائید نہیں کرتی اگر اَ نْزَلَ کے لفظ سے یہ استدلال کیا جائے کہ ہر نبی پر کتاب اُتری ہے تو یہ لفظ تو قرآن میں غیر انبیاء کے لئے بھی استعمال ہوا.پھر وہاں بھی یہی مراد لینی پڑے گی کہ انہیں بھی کتاب ملی تھی حالانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا.جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَ قَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوْۤا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (آل عمران: ۷۳) یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ مومنوں پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے ابتدائی حصہ میں تو ایمان لے آئو اور اس کے پچھلے حصہ میں اس سے انکار کر دو.شاید اس ذریعہ سے وہ بھی مرتد ہو کر اپنے دین کو چھوڑ دیں.حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ جو کچھ نازل ہوا وہ مومنوں پر نازل نہیں ہوا تھا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا.پس اَ نْزَلَ کا لفظ یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہر نبی پر مستقل طور پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ اَلْکِتَاب کا لفظ ان کے دعویٰ کو ثابت کرتا ہے.اگر ہر نبی صاحب کتاب جدیدہ ہوتا تو اَ نْزَلَ مَعَھُمُ الْکِتٰبَ کی بجائے اَنْزَلَ مَعَھُمُ الْکُتُبَ کہنا چاہیے تھا مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ نبی تو لاکھوں آئے مگر لاکھوں کتابیں نازل نہیں ہوئیں.درحقیقت اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نبی جب بھی مبعوث ہو ا ہے تو کسی نہ کسی کتاب کے ساتھ مبعوث ہوا ہے.یعنی وہ اس لئے بھیجا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کو دنیا میں قائم کرے.یہاں اس امر کا کوئی ذکر نہیں کہ ہر نبی کو کوئی نئی کتاب دی گئی تھی بلکہ صرف کتاب دیئے جانے کا ذکر ہے اور کتاب پرانی بھی ہوسکتی ہے اور نئی بھی.چنانچہ قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد متواتر انبیاء آتے رہے.مگر ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ تورات کی ترویج کریں اور اس کے احکام پر لوگوں سے عمل کروائیں.پس یہ عقیدہ کہ ہر
Page 290
نبی ضرور کوئی نئی کتاب لاتا ہے نہ صرف قرآن کریم کے خلاف ہے بلکہ انبیاء کی ایک لمبی تاریخ بھی اس عقیدہ کو واضح طور پر رد کرتی ہے.لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ میں یَحْکُمَ کی ضمیر غائب کا مرجع اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے.اور رسول اور کتاب بھی.یعنی اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے یا رسول فیصلہ کرے یا کتاب فیصلہ کرے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے آنے سے پہلے بھی لوگوں میں اختلاف موجود ہوتا ہے جسے خدایا اس کا رسول یا اس کی کتاب آکر دُور کرتے ہیں.یہ ایک غلط خیال ہے جو لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے کہ انبیاء کے آنے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اختلاف پیدا نہیں کرتے بلکہ اختلاف جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اسے مٹا کر وحدت پیدا کرتے ہیں.وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُسے پھر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اختلاف در حقیقت بعد میں ہی ہوا.پہلے اُن میں کوئی اختلاف نہ تھا مگر یہ درست نہیں.کیونکہ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ کے بعد اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ رکھ کر بتادیا ہے کہ یہ اختلاف وہ ہے جو کتاب کے بارہ میں ہے کیونکہ اُوْتُوْهُ نے بتا دیا ہے کہ یہ کتاب کا ذکر ہے.پس اس آیت میں پہلے اختلاف کا ذکر نہیں بلکہ ایک اور اختلاف کا ذکر ہے.جو نبیوں کی آمد سے پیدا ہوتا ہے.پہلا اختلاف تو وہ تھا کہ جس کے باوجود اُن کو اُمَۃً وَّاحِدَۃً کہا تھا لیکن اب صداقت کے متعلق اختلاف پیدا ہوا اور دلائل کے آنے کے بعد پیدا ہوا.اگر یہ کہا جائے کہ اس اختلاف کا تو پہلے ذکر ہی نہیں.پھر اس آیت کا یہاں کیا جوڑ ہے.تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت ایک سوال مقدر کا جواب ہے.جو پہلی آیت لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ سے پیدا ہوتاہے.اور وہ یہ تھا کہ اگر نبیوں کے بعثت کی غرض اختلاف کو مٹانا تھا تو پھر اُن کی بعثت کا کیا فائدہ ہوا انہوں نے تو آکر اور اختلاف پیدا کر دیا ؟اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ یہ اختلاف اور پہلا اختلاف مختلف ہیں.پہلا اختلاف ایسا تھا کہ جیسے مختلف بیمار ہو ںاور دوا نہ ہو.اور دوسرا ایسا ہے کہ بیمار کو دوا دی جائے اور وہ نہ پیئے.پس پہلا اختلاف مجبوری کا تھا اور اس کی تلافی ضروری تھی اور یہ اختلاف حق کے مقابلہ میں پیدا ہوا ہے.بہر حال اب حق توآگیا ہے جس کو اگر لوگ چاہیں تو مان لیں پس پہلا اختلاف خرابی ہی خرابی پیدا کرتا تھا اور یہ اختلاف ایسا ہے کہ اس میں ہدایت کی اُمید ہے کیونکہ حق موجود ہے.اب اگر اختلاف ہے تو صرف ضد کی وجہ سے ہے.دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف صرف اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ کو ہے.یعنی اس تعلیم سے جو ہم نے بھیجی ہے صرف اُن لوگوں کو اختلاف ہے جن کی طرف وہ کتاب آئی ہے یا تعلیم یا نبی آیا ہے.جو دوسرے لوگ ہیں اُن کو اِس سے
Page 291
کوئی اختلاف نہیں اور یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ اختلاف اُس نبی یا اُس کتاب یا اس تعلیم کے نتیجہ میں نہیں ہے.کیونکہ اگر فی الواقعہ وہ تعلیم جو ہم نے بھیجی ہے یا نبی جو بھیجا ہے اختلاف کا موجب ہوتے تو جو لوگ بے تعلق ہیں مثلاً غیر اقوام جو اُن کی مخاطب نہیں یا بعد میں آنے والے لوگ وہ کیوں ان کی تعلیم کی تعریف کرتے.واقعہ میں اگر دیکھا جائے تو نبیوں کی مخالفت کا زمانہ جب گذر جاتا ہے.تو لوگ اُن کی تعلیم کی بڑی تعریف کرتے ہیں.جیسے اب مسیح ؑ کی تعلیم کی لوگ تعریف کرتے ہیں.ابراہیم ؑاور موسیٰ ؑاور زرتشت ؑ کی تمام اقوام تعریف کرتی ہیں.حالانکہ اُس کتاب کی لوگ مخالفت کرتے ہیں جس میں وہ مخاطب ہوں.پس معلوم ہوا کہ اصل وجہ تعلیم یا نبی نہیں ہوتا.بلکہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کی اطاعت کس طرح کریں.یا ان احکام کو مان کر ہمارے آرام میں خلل آئے گا.جب دوسرے لوگ مخاطب ہوں تو خوب تعریف کرتے ہیں کہ واہ وا! کیا اچھی تعلیم ہے.تیسری بات بَغْیًا بَیْنَھُمْ میں یہ بیان فرمائی کہ یہ اختلاف بھی درحقیقت اس کتاب کی وجہ سے نہیں پیدا ہوا بلکہ درحقیقت پہلے اختلاف کا نتیجہ ہے.نبی آنے سے پہلے جو سرکشی اور عداوت آپس میں لوگوں کی پیدا ہو چکی تھی وہی اس تعلیم کی مخالفت پر لوگوں کو آمادہ کر رہی ہے.یا یہ سوال ہے کہ اس نبی کو ہم کیونکر مان لیں ؟ یا یہ کہ فلاں نے اِسے مان لیا ہے اب ہم کس طرح مان لیں؟ یا یہ فلاں عقیدہ کی جو ہمارے دشمنوں کا ہے تائید کرتا ہے.اس کو مان لیں تو اُن کے سامنے ہماری نظریں نیچی ہو جائیں.جیسے حنفی کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہابیوں کی فلاں فلاں باتوں کی تائید کی ہے اس لئے ہم انہیں نہیں مانتے.اِسی طرح وہابی کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے حنفیوں کی بعض باتوں کی تائید کی ہے اس لئے ہم آپ کو قبول نہیں کر سکتے.پس نبی کو نہ ماننے کی وجہ وہ عداوت ہوتی ہے جو اس نبی کے آنے سے پہلے اُن میںموجود ہوتی ہے.حقیقت یہ ہے کہ نبی کے آنے کے بعد ایک جماعت ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والی اور اس کے احکام پر عمل کرنے والی ہوتی ہے اس لئے گو اس کے آنے سے بھی اختلاف نظر آتا ہے.لیکن روحانی نگاہ رکھنے والا جانتاہے کہ نبی کے آنے سے اختلاف کی قوت کم ہو جاتی ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دور رہنے والے لوگ گھٹ جاتے ہیں اور ایک بڑی جماعت ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو خدائے واحد کی پرستار ہوتی ہے.غرض اختلاف اس کتاب کے سبب سے نہیں بلکہ پہلے اختلاف کے باعث لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیںجو ان لوگوں کے اندر پہلے سے موجود تھایا یہ کہ وہ بَـغِیْ جو بَیْنَھُمْ ہے.یعنی ساری کی ساری اُنہی کے قبضہ میں ہے.ہمارے رسولوں اور اُس کے اتباع میں اس کا کوئی حصہ نہیں وہ اس اختلاف کا باعث ہے.اس سے الزام اور بھی سخت ہو جاتا ہے کہ یہ بغی کرتے
Page 292
ہیں باوجود اس کے کہ دوسری طرف سے اُن کی خیر خواہی اور ترقی کے سامان ہو رہے ہیں.فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ.اس میں چوتھا جواب دیا ہے کہ اختلاف کا الزام نبیوں پر نہیں آسکتا اور وہ یہ کہ اُن کے آنے سے پہلے تو دیکھو کہ کوئی بھی حق کا ماننے والا نہ تھا.مگر اب ایک پارٹی تو حق کو مانتی ہے.پس اختلاف درحقیقت مٹ گیا پیدا نہ ہوا.کیونکہ پہلے مثلاً ایک لاکھ آدمی خدا تعالیٰ کے متعلق اٹکل پچو باتیں بنا رہے تھے.اب ایک ہزار نے مان لیا اور ننا نوے ہزار نے نہ مانا تو اختلاف کم ہوا یا زیادہ.ایک ہزار آدمی اس خیالی اختلاف سے نکل کر یقین اورو ثوق کے مقام پر آکھڑے ہوئے جہاں سے اللہ تعالیٰ کے جلال کا مشاہدہ ہوتا ہے.پس اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس چیز کی طرف ہدایت دی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا یعنی جس کا ذکر وَ مَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ میں ہوا تھا.اِخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ میں فِیْہِ کی جو ضمیر ہے الْـحَقّ اُس کی صفت ہے.یعنی اُس چیز کی طرف جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اور جس کی صفت یہ ہے کہ وہ حق ہے یا حق میں سے ہے.یا مِنْ بیان کےلئے ہے اور معنے یہ ہیں کہ ہدایت کی اُس چیز کی طرف جس کی نسبت لوگوں نے اختلاف کیا تھا حالانکہ وہ حق تھی.یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پہلے ہی مومن تھے تو ھَدَی اللّٰہُ کے کیا معنے ہوئے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی پچھلی بات کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ نام لے لیا کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں یہ بادشاہ جب پیدا ہوا تو یوں ہوا.حالانکہ وہ پیدائش کے وقت بادشاہ نہیں ہوتا.یا کہتے ہیں یہ عالم جب سکول میں پڑھنے گیا.پس اَ لَّذِیْنَ اٰمِنُوْااُن کا موجودہ نام ہے جس کو پرانے واقعہ کو دہراتے وقت قائم رکھا.تاکہ اُن کا احترام قائم رہے اور اُن کی طرف کفر کسی وقت بھی منسوب نہ ہو.یا یہ کہ استعداد مخفی جواُن کے اندر تھی اس کو مدّ نظر رکھتے ہوئے ا نہیں الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کہا گیا ہے.یعنی وہ جو مومن بننے والے تھے اور اس کےلئے سامان بہم پہنچا رہے تھے.فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِہٖ میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگوں نے کتاب الٰہی کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے اُن سب وعدوں کو جو اس نبی کے ذریعہ سے اپنی قوم کے متعلق تھےمٹھی بھر مومنوں کے حق میں پورا کر دیا اور مومنوں کو وہ کامیابیاں دے دیں جو سب قوم کے لئے مقدر تھیں.اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ ہر شخص کے دو گھر ہیں ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں جب کوئی ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ظالم کا جنت کا گھر مومن کو اور اس کا دوزخ کا گھر کافر کو دے دیتا ہے.کفار نے چونکہ بلاوجہ کتابِ الٰہی کی مخالفت کی اور اس کے سبب سے مومنوں کو سخت دُکھ برداشت کرنے پڑے خدا تعالیٰ نے
Page 293
حکم دے دیا کہ وہ انعامات جو ساری قوم کے لئے مقدر تھے وہ مٹھی بھر مسلمانوں کو دے دیئے جائیں اور باقی قوم کو بوجہ ظالم ہونے کے ان سے محروم کر دیا جائے.اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ تم پر ابھی ان لوگوں کی (سی تکلیف کی) حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ١ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ گذرے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤگے.انہیں تنگی بھی پہنچی اور تکلیف بھی.اور انہیں خوب خوف دلایا گیا تاکہ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ (اس وقت کا) رسول اور اس کے ساتھ (کے) ایمان لانے والے کہہ اٹھیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللّٰهِ١ؕ اَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ۰۰۲۱۵ یاد رکھو اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے.حلّ لُغات.مَسَّتْھُمْ مَسَّ الشَّیْءَ کے معنے ہیں لَمَسَہٗ وَاَفْضٰی اِلَیْہِ بِیَدِہٖ مِنْ غَیْرِ حَائِلٍ کسی چیز کو بغیر کسی درمیانی روک کے اس نے چُھوا.(اقرب) بَاْسَآء کے معنے ہیں اَلشِّدَّۃُ سختی وَاِسْمٌ لِلْحَرْبِ وَالْمُشَقَّۃِ وَالضَّرْبِ.اور بَاْسَاء کے لفظ کا اطلاق جنگ اور مشقت اور جسمانی تکالیف پر بھی ہوتا ہے.(اقرب) ضَرَّآءُ کے معنے ہیں اَلزَّمَانَۃُ وَالشِّدَّۃُ قحط.اَلنَّقْصُ فِی الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ.مالی اور جانی نقصان.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں ان ابتلائوں کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں پر آنے والے تھے.چونکہ اس سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ جب دنیا پرضلالت چھا جاتی ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی آتا ہے جس کی لوگ مخالفت کرتے ہیں.اس لئے اب فرماتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بغیر ابتلائوں کے تم ترقی کر جائو گے.تمہاری ترقی ابتلائوں کے آنے پر ہی موقوف ہے جیسا کہ پہلوں کی ترقی کا باعث بھی ابتلاء ہی ہوئے.چنانچہ اس کا نقشہ کھینچتے
Page 294
ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہمَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ.انہیں مالی مشکلات بھی پیش آئیں اور جانی بھی اور وہ سرسے پائوں تک ہلادیئے گئے اور ان پر اس قدر ابتلاء آئے کہ آخر اس وقت کے رسول اور مومنوں کو دُعا کی تحریک پیدا ہو گئی اور وہ پکار اُٹھے کہ اے خدا! تیری مدد کہاں ہے؟ اس آیت کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے پاک بندے بھی کسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسے مایوس ہو جاتے ہیں کہ انہیں مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ کہناپڑتا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ جس مایوسی کا تصور بادی النظر میں پیدا ہوتا ہے اس سے انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے کلیۃً پاک ہوتے ہیں.جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ (یوسف: ۸۸) کہ صرف کافر ہی خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہوتے ہیں.بات یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب مَتٰی کا لفظ بولیں تو اس سے مراد مایوسی نہیں ہوتی بلکہ تعیین کے لئے ایک درخواست ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں بات کے لئے ایک وقت مقرر فرماد یا جائے.ایسا ہی اس جگہ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ کے یہ معنے نہیں کہ وہ مایوسی کا شکار ہو کر ایسا کہتے ہیں بلکہ درحقیقت ان الفاظ میں وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ الہٰی اس بات کی تعیین فرما دی جائے کہ وہ مدد کب آئےگی؟ گویا مزید اطمینان کے لئے وہ آنے والی نصرت کے وقت کی تعیین کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جلد نازل ہو.یہ دُعا کا ایک موثر طریق ہے اور اس میں یہ اشارہ مخفی ہے کہ ان پر اس قدر ابتلاء آئے کہ وہ ہلادیئے گئے اور ان میں دُعا کی تحریک پیدا ہو گئی.اور ابتلائوں کی بڑی غرض بھی یہی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جب مومنوں کو دعا کی تحریک ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ آسمان سے اپنی نصرتِ نازل فرما دیتا ہے.اور ان کے مصائب کا خاتمہ کر دیتا ہے.مگر اس کے علاوہ حتّٰی کے معنے ’’کَی‘‘ کے بھی ہوتے ہیں اور یہ معنے کُتب نحو اور قرآن کریم سے ثابت ہیں.مغنی اللبیب میںلکھا ہے.وَمُرَادِفَۃُ کَیِ التَّعْلِیْلِیَّۃِ حَتّٰی یعنی حَتّٰی کے معنے اس ’’کَی‘‘ کے مترادف بھی ہوتے ہیں جو کسی بات کی وجہ بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اس حتّٰی سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ بعد میں آنے والی بات کے لئے بطور سبب کے ہوتی ہے.قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی حتّٰی ان معنوں میں آیا ہے.چنانچہ سورۃ منافقون میں آتا ہے هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا (المنافقون : ۸)یعنی جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرو.تاکہ وہ بھاگ جائیں.نحوی اس کی یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ اَ سْلِمْ حَتّٰی تَدْ خُلَ الْجَنَّۃَ یعنی فرمانبرداری کرتا کہ تو جنت میں داخل ہو جائے.ان معنوں کے لحاظ سے
Page 295
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ زلزلہ جو کفار کے ہاتھوں سے ہم نے پیدا کیا اس کی غرض ہی یہ تھی کہ ہمارے بندے ہم سے مانگیں اور ہم ان کو دیں.پس مانگنے کی طرف توجہ پھیرنے اور اپنی قوتِ فضل کو ظاہر کرنے کے لئے اس وقت تک ہم چُپ رہے جب تک کہ ان کے دل میں دعا کی زور سے تحریک پیدا نہ ہوئی.اور یہ تحریک ہم نے خود کروائی تاکہ ایک طرف ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے اور دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کی نصرت معجزانہ طور پر آئے تو ان کے ایمان بڑھیں اور کفار میں سے جو غور کرنے والے ہوں انہیں ہدایت حاصل ہو.چنانچہ فرماتا ہے کہ جب یہ غرض پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ لو اب ہماری مدد آگئی.ابتلائوں کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ انسان کی ہمت دیکھ کر ابتلا ء ڈالتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ابتلاء انسان پر ڈالے جن کے برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہی نہ ہو.ہاں انسان ایسے ابتلائوں میں ضرور ڈالا جاتا ہے جن کے متعلق وہ غلطی سے خیال کرلیتا ہے کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکوں گالیکن اس کا یہ خیال درست نہیں ہوتا وہ ان کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے.اسی لئے خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا(البقرۃ:۲۸۷) یعنی خدا تعالیٰ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اُٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو.بوجھ ہمیشہ وہی ڈالا جاتا ہے جس کے اُٹھانے کی انسان میں طاقت ہوتی ہے.سوائے اس کے کہ کسی قوم کو تباہ کرنے کا منشا ہو.ورنہ جو ابتلاء کسی جماعت کی ترقی کے لئے ہوتے ہیں وہ طاقت برداشت سے باہر نہیں ہوتے.ہاں مومن بعض دفعہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ اس کی طاقت سے بالا ہیں.مگر یہ اس کی غلطی ہوتی ہے جب مومن ایک ابتلاء کو برداشت کر لیتا ہے تو اُسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے پھر اور رنگ میں اس پر ابتلاء آتا ہے اور وہ اُسے بھی برداشت کر لیتا ہے اور اس کے دل میں کسی قسم کا شکوہ پیدا ہونے کی بجائے شکرو امتنان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے.کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں نے اسے برداشت کر لیا تب اس کا ایمان اور بھی پختہ ہو جاتا ہے اور وہ اس سے بڑے بڑے ابتلاء برداشت کر نے کے لئے تیار ہو جاتا ہے.غرض جوںجوں انسان دلیر ہوتا جاتا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے اس طرح ایک تو اسے اپنے ایمان کی پختگی کا پتہ لگ جاتا ہے.دوسرے قربانیوں کے میدان میں اُسے دوسروں سے آگے بڑھنے کا موقعہ مل جاتا ہے اور وہ ترقی کر جاتا ہے.غرض ابتلاء کے دو فائدے ہوتے ہیں.اوّل یہ کہ انسان کو اپنی حالت کا پتہ لگتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کی جان کس قدر تکلیف اُٹھا سکتی ہے.دوسرے اس میں آگے قدم بڑھانے کی جرأت پیدا ہوتی ہے.ان ابتلائوں کا آنا ایسا ضروری ہے کہ نبیوں کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہوئی جس پر ابتلاء نہ آئے ہوں.اسی لئے اللہ تعالیٰ
Page 296
فرماتا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ جنت جس کی وسعت کا اندازہ بھی تم نہیں لگا سکتے تمہیں یونہی مل جائےگی یا وہ دنیوی کامیابیاں جن کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے بغیر قربانیوں کے تمہیں مل جائیں گی اور تم پر وہ حالت نہیں گذرے گی جو پہلوں پر گذرتی رہی.ایسا کبھی نہیں ہو سکتا.وہ حالت ضرورآئے گی.اس لئے یہ مت خیال کرو کہ تم آسانی سے کامیاب ہو جائو گے.جب تک تم ان حالتوں میں سے نہیں گذرو گے جن میں سے پہلے لوگ گذرے اس وقت تک تمہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی.انہیں بڑی بڑی تکالیف پہنچی تھیں جسمانی بھی اور مالی بھی.انہیں اپنی جائیدادیں چھوڑنی پڑیں.رشتہ داروں کو ترک کرنا پڑا.فاقے کرنے پڑے.ماریں کھائیں.قتل ہوئے.غرض وہ کئی رنگ میں ہلائے گئے جس طرح زلزلہ سے عمارت کبھی دائیں طرف جھکنے لگتی ہے اور کبھی بائیں طرف اسی طرح دیکھنے والے ان کے متعلق یہی سمجھتے تھے کہ یہ اب گِرے کہ گِرے حتّٰی کہ ان کی تکالیف بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئیں کہ دشمن نے یہ خیال کر لیا کہ اب یہ گِر ہی گئے ہیں.اس وقت اللہ تعالیٰ کے رسول اور مومنوں نے دعائیں کرنی شروع کیں کہ مَتٰى نَصْرُ اللّٰہِ.اے خدا! ابتلاء اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی مدد آئے اور ہمیں کامیابی عطا کرے.مَتٰى نَصْرُ اللّٰہِ کے لفظی معنے چونکہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئےگی.اس لئے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ کی مدد کے متعلق نعوذ باللہ شبہ پیدا ہو گیا تھا.کہ شاید وہ آئے یا نہ آئے اس لئے انہوں نے کہا کہ خدا یا! تیری مدد کب آئے گی؟ مگر یہ صحیح نہیں اوّل تو مَسَّتْـھُمْ میں مَسَّ کا لفظ دومعنوں میں استعمال ہوا ہے.ایک یہ کہ عملاً ان کو مشکلات پہنچیں اور دوسرے یہ کہ وہ مشکلات دل پر اثر کرنے والی نہیں تھیں صرف سطحی تھیں ان کے دل مضبوط تھے پس جب مشکلات کے باوجود وہ بہادر دل تھے تو ان کے متعلق کسی مایوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا.دوسرے سوال کبھی التجاء کا رنگ بھی رکھتا ہے انسان کسی سے پوچھتا ہے کہ یہ بات آپ کب کریںگے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نہیں کریںگے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کردیں.اسی طرح مجسٹریٹ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ میری باری کب آئے گی تو اس کے یہ معنے نہیں ہوتے کہ کبھی نہیں آئے گی.بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آجائے.بدر کے موقعہ پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے خدا! اگر یہ مختصر سا گروہ بھی ہلاک ہو گیا تو دنیا میں تیری عبادت کون کرے گا(مسند احمد بن حنبل ،مسند عمر بن الخطاب).تو اس کے یہ معنے نہیں تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذباللہ خدا تعالیٰ پر یقین نہیں تھا بلکہ اس رنگ میں دُعا کر کے آپؐ نے خدا تعالیٰ کی
Page 297
غیرت کو برانگیختہ کیا.اسی طرح حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے جب صلیب پر لٹکتے وقت کہا کہ ایلی ایلی لماسبقتنی (متی باب ۲۷ آیت ۴۶) یعنی اے خدا! چاہیے تو یہ تھا کہ اس مصیبت کے وقت تو میری مددکےلئے آتا لیکن تُو تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے تو آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ مصیبت کے وقت انہیں واقعہ میں چھوڑ گیا ہے.بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے آپ جلدی میری مدد کے لئے آجائیں پس اس رنگ میں جب دُعا کی جاتی ہے تو قبولیت دُعا پر عدِم یقین کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ کو غیرت دلانے کے لئے ہوتی ہے اسی طرح جب مومن کہتے ہیں مَتٰى نَصْرُ اللّٰہِ اے خدا! تیری مدد اور نصرت کب آئےگی تو خدا تعالیٰ کہتا ہے سُنو.میری مدد آپہنچی.چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم جب فتح مکہ کے لئے تشریف لے گئے تو مکہ والوں کو خیال تک بھی نہیں تھا کہ آپ ان پر حملہ آور ہوںگے.ابوسفیان خود آپ سے مدینہ میں مل کر آرہا تھا.جب لوگوں نے آپ کا لشکر دیکھا تو بعض نے کہا کہ یہ لشکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ہو گا.اس پر ابوسفیان نے کہا.تم پاگل تو نہیں ہو گئے میں ابھی مدینہ سے آرہا ہوں.وہاں کوئی لشکر تیار نہیں تھا.مگر اگلے ہی چار پانچ منٹ میں مسلمان اُس کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے ابوسفیان کو گرفتار کر لیا اور دوسرے دن مکہ فتح ہو گیا.غرض خدا تعالیٰ کی نصرت اچانک آتی ہےاور مومنوں کو کامیاب کر دیتی ہے.عیسائیوں نے تین سو سال تک بڑے بڑے مصائب برداشت کئےلیکن ایک دن انہوں نے سُنا کہ روم کا بادشاہ عیسائی ہو گیا ہے اورآئندہ سے ملک کا مذہب عیسائیت ہو گا اور اس اعلان کے ساتھ ہی ان کے تمام مصائب ختم ہو گئے.غرض مَتٰى نَصْرُ اللّٰہِ.میں یہ بتایا ہے کہ مومن دُعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ الہٰی ابتلاء بڑھ گئے ہیں اب تیری مدد آجائے.اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہےاَلَاۤ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ.سُنو! خدا کی مدد قریب ہی ہے یعنی جب ابتلاء تمہاری ترقیات کے لئے آئیں تو پھر تمہیں تباہ ہونے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے.اگر تمہارے نفسوں میں خرابی ہے اور تم جانتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں سزا دینا چاہتاہے تو پھر یقیناً تمہارے لئے مدد نہیں آئےگی.لیکن اگرتمہارے نفسوں میں کوئی خرابی نہیں تمہارا ایمان مضبوط ہے تم تقویٰ کی راہ پر قدم ماررہے ہو.وساوس پر تمہیں قابو حاصل ہے تو ابتلاء تمہارے لئے خوف و خطر کا باعث نہیں ہوسکتے.درحقیقت ایک سچے مومن پر جب ابتلاء آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس ابتلاء کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی مدد بھی آرہی ہے.مولانا رومؒ نے اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے کہ؎
Page 298
ہر بلا کیں قوم را حق دادہ است زیر آں گنجِ کرم بنہادہ است (مثنوی معنوی للرومی ذکر کرامات شیبان الراعی صفحہ ۱۱۳) یعنی جب کسی قوم پر کوئی آزمائش کا وقت آتا ہےتو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے نیچے انعامات کا ایک بہت بڑا خزانہ مخفی ہوتا ہے.پس ابتلاء کسی خطرہ کا موجب نہیں ہوتے بلکہ ابتلاء کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اور ترقی عطا کرے گا.ڈر اور خوف صرف اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے.پس ہمیشہ اپنے نفس پر غور کرتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں کوئی ایسی بات تو پیدا نہیں ہو گئی جو تباہی کا باعث بن جائے.اگر اس میں وساوس پیدا نہیں ہوتے اگر ایمان مضبوط ہے اور دل شکر اور امتنان کے جذبات سے پُر ہے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے کیونکہ ایسی حالت میں ابتلاء بہت بڑے انعامات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں.لیکن اگر ابتلاء آنے پر دل میں وساوس پیدا ہوں اور ایمان میں کمزوری محسوس ہو تو سمجھ لو کہ یہ ابتلاء ترقی کا باعث نہیں بلکہ ہلاکت کا باعث ہیں.غرض اصل اور حقیقی ایمان وہی ہوتا ہے جو ابتلائوں میں سے گذرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے.کیونکہ اسی کے نتیجہ میں ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے.يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ١ؕ۬ قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تو کہہ دے (کہ )جو اچھا مال بھی تم دو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ وہ (تمہارے )ماں باپ قریبی رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافر کا السَّبِيْلِ١ؕ وَ مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ۰۰۲۱۶ (پہلا) حق ہے.اور جو نیک کام بھی تم کرو اللہ اسے یقیناً اچھی طرح جانتا ہے.تفسیر.چونکہ گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ پہلے لوگوں پر بھی مالی اور جانی مشکلات آئی
Page 299
تھیں اور وہی ان کی قومی ترقی کا باعث ہوئیں جیسا کہ مَسَّتْـھُمُ الْبَاْسَآئُ وَالضَّرَّآئُ کے الفاظ سے ظاہر ہے.اس لئے جب صحابہؓ نے یہ بات سنی تو ان کے دل بھی ان قربانیوں کے لئے بے تاب ہو گئے اور انہوں نے بے اختیار ہو کر روحانی ترقیات کے حصول کےلئے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! اگر قومی ترقی کے لئے مالی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہم کیا خرچ کریں تاکہ ہمارا قدم بھی عشق کے میدان میں کسی دوسرے سے پیچھے نہ رہے.دوسراسوال جانی قربانیوں کے متعلق ہو سکتا تھا.سو اس کا جواب کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ میں دیا گیا ہے جس سے قرآن کریم کی نہایت اعلیٰ درجہ کی ترتیب پر روشنی پڑتی ہے.اس آیت کے متعلق لوگ عام طور پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہے اور جواب کچھ ہے.پوچھا تو یہ گیا ہے کہ کیا خرچ کریں؟ اور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی اپنے اموال میںسے خرچ کرو.وہ فلاںفلاں کو دو.اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض قلّتِ تدبر کی وجہ سے ہے سوال کا جواب آیت میں موجود ہے جب اس نے فرما دیا کہ جو کچھ بھی تم اچھے مال سے خرچ کرو تو اس میں سائل کا جواب مکمل آگیا.اوّل یہ کہ کوئی حد بندی نہیں.جتنے کی توفیق ہوا تنا خرچ کرو.دوم یہ ہے کہ اس امر کا لحاظ رکھو کہ جو خرچ کرو وہ طیب مال ہو.جو لوگ حرام کماتے ہیں اور اس میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہ کا کفارہ کردیا وہ غلطی پر ہیں.خدا تعالیٰ ایسے ہی مال کو قبول کرتا ہے جو اچھا ہو.سوم یہ کہ صرف حلال نہیں دینا بلکہ طیّب دینا ہے یعنی جس مال کو قبول کرنا اس شخص پر گراں نہ گذرے جس کو مال دیا جائے.ممکن ہے کوئی کہے کہ خیر کے معنے مال کے ہیں.اچھے مال کے معنے کہاں سے نکالے گئے ہیں.تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیر کے اصل معنے بہترین شے کے ہیں.اور مال کو اسی صورت میں خیر کہتے ہیں جب کہ وہ طیّب ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو.مفرادتِ راغب میں ہے وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَا یُقَالُ لِلْمَالِ خَیْرٌ حَتّٰی یَکُوْنَ کَثِیْرًا وَمِنْ مَکَانٍ طَیِّبٍ.یعنی مال کو خَیْر اسی صورت میں کہیں گے جبکہ وہ زیادہ ہو اور پاک ذرائع سے حاصل کیاگیا ہو.اور خود طیّب ہو پس خیر کہنے سے یقیناً قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ طیب اموال میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو.اگر کہا جائے کہ اگر کوئی شخص حرام کماتا ہو لیکن صدقہ طیب مال سے دے تو کیا یہ اس حکم کے مطابق ہو گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تھوڑی سی گندگی بھی بہت سی پاکیزہ شے کو گندہ کر دیتی ہے.پس اگر کوئی شخص رشوت لیتا یاچوری کرتا یا ظلم سے دوسرے کا مال لیتا ہے تو خواہ اس قسم کا مال تھوڑا ہو اس کا سب مال گندہ ہو جائےگا اور وہ اس حکم کو پورا کرنے والا نہ ہوگا.غرض سوال کا مکمل جواب اسی آیت میں
Page 300
آگیا.ہاں اس سے زائد مضمون بھی بتا دیاگیاکہ اگر خرچ کرو تو کہاں کہاں خرچ کرو.گویا اس طرف اشارہ کیا کہ خرچ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ صحیح جگہ خرچ کرنا مشکل ہے.پس جو خرچ کرو احتیاط سے کرو اور مستحقین کو دو.یہ قرآنی کمال ہے کہ وہ مختصر الفاظ میں وسیع مضمون بیان کردیتا ہے.دیکھو یہاں کتنے مختصر لفظوں میں سوال کا جواب بھی دے دیا.یہ بھی بتا دیا کہ مال حلال دو(طیّب میں حلال کا مفہوم بھی شامل ہے) اور یہ بھی کہ حلال مال طیب بھی ہو.یہ نہیں کہ ٹوٹی ہوئی جوتی جو کسی کام کی نہیں دےدی بیشک وہ اس کا مال ہے.بے شک اس کا دینا اسے حلال ہے مگر وہ طیّب نہیں.کیونکہ جسے دی گئی ہے اس کے کام کی نہیں.یا مثلاً ایک بھوکا کھانا مانگنے آیا ہے گھر میں کھانا تیار ہے مگر اُسے آٹا دے دیا.یہ مال بھی ہے حلا ل بھی ہے.مگر بھوکے کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا.طیب یہ ہے کہ خود کم کھائے اسے پکا ہوا کھانا دے جسے وہ فوراً کھا سکے.یہ سب کچھ بتا کریہ بھی بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ مال خرچ کرنا زیادہ مناسب ہے.سبحان اللہ کیا معجزانہ اعجاز ہے!! قرآن مجید میں ایسی مثالیں اور بھی ہیں کہ سوال کا جواب دے کر زائد مضمون بتا دیا ہے.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام فرماتے تھے.آپؐ سے کسی نے پوچھا کہ سمندر کے پانی کے بارہ میں کیا حکم ہے.آپ ؐ نے فرمایا ھُوَ الطَّھُوْرُ مَاءُ ہٗ وَ الْحِلُّ مَیْتَتُہٗ.(ترمذی ابواب الطہارۃ باب ما جاء فی ماء البحر انہ طھور)اس کاپانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے یعنی سمندری جانور کے لئے ذبح کرنے کی شرط نہیں.جیسے مچھلی، اب دیکھو! یہاں سوال کا جواب بھی دیا ہے اور زائد مضمون بھی بتا دیا ہے.یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا خرچ کرنے کے الفاظ سے صدقہ کے اقسام کا دریافت کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارا خرچ کرنا کس کس موقعہ اور کن کن لوگوں کے لئے ہو.اور اس جگہ غالباً یہی مراد ہے.کیونکہ کمیت کے متعلق سوال آگے آتا ہے.مَاذَا سے سوال کبھی اُس چیز کے متعلق کیا جاتا ہے اور کبھی اس کی صفات کے متعلق.نحوی لکھتے ہیں کہ صفات کے متعلق صرف ذوی العقول کے بارہ میں سوال کیا جاتا ہے.لیکن یہ حد بندی بلاوجہ معلوم ہوتی ہے میرے نزدیک اس جگہ پوچھنے والا یہ نہیں پوچھتا کہ صدقہ کس چیز کا ہو.بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ صدقہ کی صفات کیا ہوں؟ سوا للہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ معین نہیں ہر اچھی چیز خرچ کرو.یعنی طیّب مال سے ہو اور جتنی توفیق ہو اس قدر دیا جائے اور ساتھ ایک بات زائد بتا دی کہ تم اپنے ایمان یا اپنی حالت کے ماتحت جو کچھ خرچ کرو.یہاں یہاں خرچ کرو.پھر فرمایا مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰہَ بِہٖ عَلِیْمٌ.اللہ تعالیٰ کے قرب کے لئے تم کسی ایک نیکی پر حصر نہ کرو.بلکہ ہر قسم کی نیکیاں بجا لائو.اور ہر خیر اور برکت کا دروازہ اپنے اوپر کھولنے کی کوشش کرو.کیونکہ تمہارے سامنے ایک
Page 301
لامتناہی زندگی ہے جس میں تمہاری روح نے قربِ الہٰی کی باریک درباریک راہوں پر چلنا ہے.پس کسی ایک یا چند نیکیوں پر اکتفا نہ کرو بلکہ خیر میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو.اور اس امر پر یقین رکھو کہ ایک علیم ہستی تمہاری ہر حرکت اور سکون کو دیکھ رہی ہے.وہ تمہیں دنیا و آخرت میں اس کا بہترین اجر دے گی.كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ١ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ جنگ کرنا تم پر فرض کیا جاتا ہے (اور) اس حالت میں (فرض کیا جاتا ہے)کہ وہ تمہیں ناپسند ہے.اور بالکل ممکن تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ١ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے بہتر ہو.اور یہ (بھی) ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرتے هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَؒ۰۰۲۱۷ ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے دوسری چیز کی نسبت بری ہو.اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.تفسیر.اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہؓ لڑائی کو اس لئے نا پسند کرتے تھے کہ وہ نعوذباللہ بُزدل تھے.بلکہ ان کی ناپسندیدگی کی وجہ صرف یہ تھی کہ مومن صلح پسند ہوتا ہے اور اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لڑائی نہ ہو اور صلح سے فیصلہ ہو جائے اور اگر وہ اپنے دشمن سے لڑتا ہے تو مجبوراً لڑتا ہے.صحابہؓ بھی دل سے صلح جُوتھے اور وہ چاہتے تھے کہ اگر کُشت و خون کے بغیر یہ فتنہ دب سکے تو دب جائے مگر انہیں مجبوراً لڑائی لڑنی پڑی.پس یہ صحابہؓ کی تعریف ہے نہ کہ ان کی مذمت.یہ ان کی بُزدلی نہیں بلکہ یہ قابل تعریف امر ہے کہ باوجود دشمنوں کے شرارتوں کے وہ یہی چاہتے تھے کہ اگر صلح سے فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے.چنانچہ فرمایا.تم تو نہیں چاہتے تھے کہ لڑو حالانکہ دشمن تم پر ظلم پر ظلم کر رہا تھا.اور تمہیں مار رہا تھا مگر میں جانتا تھا کہ یہ دشمن بغیر لڑائی کے باز آنے والے نہیں.اس لئے اب ان کی اصلاح کا یہی ذریعہ ہے کہ ان سے لڑا جائے اور انہیں ان کے کئے کا مزا چکھایا جائے.عیسائیوں نےاس آیت سے دھوکا کھاتے ہوئے اعتراض کیا ہے کہ مسلمان چونکہ لڑائی سے ڈرتے تھے اس لئے معلوم ہوا کہ وہ بزدل اور ڈر پوک تھے.(تفسیر القرآن از وہیری زیر آیت ھذا) مگر صحابہؓ کو بزدلی کا طعنہ دینے والے عیسائی یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اپنے حواری کیسے بہادر اور دلیر تھے اور انہوں نے مسیح کی گرفتاری کے وقت کیسی
Page 302
جرأت کا مظاہرہ کیا؟ انجیل گواہ ہے کہ کوئی ایک حواری بھی ایسا نہیں نکلا جس نے دلیری سے مسیح کا ساتھ دیا ہو بلکہ ایک حواری نے توآپ پر تین دفعہ لعنت کی اور باقی سب اُس انتہائی نازک گھڑی میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے.ایسے باایمان اور دلیر حواریوں کو مقدس قرار دینے والے عیسائی اگر صحابہؓ پر اعتراض کریں تو ان کی عقل پر تعجب آتا ہے پھر عیسائیوں کی یہ ایک عجیب عادت ہے کہ صحابہؓ کے لڑائی پر جانے کا ذکر ہو تو بھی اعتراض کرتے ہیں اور نہ جانے کا ذکر ہو تب بھی اعتراض کرتے ہیں.جہاں غنیمت کا ذکر آتا ہے وہاں کہنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان بڑے لالچی تھے مال کی لالچ کے لئے لڑتے تھے اور اس موقعہ پر لکھتے ہیں کہ وہ بڑے بزدل تھے.لڑائی سے ڈرتے تھے حالانکہ اگر ان کی لڑائی لوٹ مار کے شوق کے لئے تھی تو پھر کراہت کیسی اور اگر کراہت تھی تو پھر شوق کیسا؟ اصل بات یہ ہے کہ غلط معنے کر کے انسان اضداد میں پھنس جاتاہے.بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ مومن صلح پسند ہوتا ہے اسے اگر مجبور کیا جائے تو وہ لڑتا ہے ورنہ وہ یہی پسند کرتا ہے کہ لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہوں.پھر فرماتا ہے.عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ١ۚ وَ عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ درحقیقت انسانی علم اور سمجھ نہایت ہی محدود ہے اور ان دونوں کے محدود ہونے کی وجہ سے انسان بعض دفعہ ایک بات کو اپنے لئے مفید سمجھتا ہے.حالانکہ وہ اس کےلئے مضر ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ ایک بات کو اپنے لئے مضر خیال کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے لئے مفید ہوتی ہے اور دونوں کے پیچھے یا توجذبہ محبت کا ناجائز استعمال کام کر رہا ہوتا ہے یا جذبہ نفرت کا ناجائز استعمال کام کر رہا ہوتا ہے.یعنی بعض دفعہ تو شدید محبت کی وجہ سے وہ کسی چیز کے مضرات کو نہیں دیکھ سکتا اور بعض دفعہ شدید نفرت کی وجہ سے وہ دوسری چیز کے حسن کو دیکھنے سے قاصر رہتا ہے اور وہ یقینی طور پر کسی امر کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آیا وہ میرے لئے مفید ہے یا مضر.اس حالت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن حقیقتاً وہ تمہارے لئے مفید ہوتی ہے اور بعض دفعہ تم ایک چیز کو مفید خیال کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لئے مضر ہوتی ہے تم کبھی کسی چیز سے فوائد حاصل کرنے کے لئے سامان مہیا کرتے ہو لیکن پھر بھی نتیجہ خراب نکلتا ہے.جس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ بعض ایسے سامان جن سے اچھا نتیجہ نکل سکتا تھا تمہاری نظر سے مخفی رہے پس جبکہ انسان کی ایسی حالت ہے کہ اس کی امید کے مطابق ہر وقت اچھے نتیجے نہیں نکلتے بلکہ بعض اوقات بُرے نتائج نکل آتے ہیں تو وہ کیا کرے؟ سو اس کا علاج یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور گرے اور عاجزی سے یہ دعا کرے کہ اِھْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ اے خدا ! مجھ کوہرامر میں خواہ وہ دینی ہو یا دنیوی صحیح اور سیدھا راستہ دکھاتا میں غلطیوں سے محفوظ رہوں.اور اپنی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو نہ دیکھے بلکہ محبت اور نفرت کے جذبات سے بالا ہوکر
Page 303
صرف اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی نگاہ رکھے اور اس سے دعائیں کرتا رہے کہ وہ اسے سیدھا راستہ دکھائے اور اپنی نیت اورارادہ کو اللہ تعالیٰ کے منشاء کے تابع کر دے.تب اس کے لئے کامیابی ہی کامیابی ہو گی اور خیر اور برکت کے دروازے اس کے لئے کھولے جائیں گے.آخر میں وَاللّٰہُ یَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ کہہ کر بتایا کہ تم تو نہیں جانتے لیکن خدا تعالیٰ تمام حالات کو جانتا ہے.یعنی تم کفار سے لڑائی کرنا رحم کے خلاف سمجھتے ہو.حالانکہ بعض دفعہ شریر کو سزا دینا اس کی اصلاح کے لئے ضروری ہوتا ہے اور اس کو چھوڑ دینا خود اس کے لئے اور دوسرے لوگوں کے لئے مضر ہوتا ہے.پس چونکہ یہ لوگ اب بغیر جنگ کے باز آنے والے نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا مقابلہ کیا جائے.يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ١ؕ قُلْ قِتَالٌ یہ(لوگ) تجھ سے حرمت والے مہینہ کے بارہ میں یعنی اس میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں.تو کہہ فِيْهِ كَبِيْرٌ١ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ دے (کہ )اس میں جنگ کرنا بڑی (خرابی کی) بات ہے.اور اللہ کے راستہ سے روکنا اور اس کا( یعنی اللہ کا) اور الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ١ۗ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ١ۚ وَ عزت والی مسجد کا انکار کرنا اور اس کے باشندوں کو اس میں سے نکال دینا اور اللہ کے نزدیک( اس سے بھی ) الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ١ؕ وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ بڑی بات ہے.اور فتنہ (و فساد) قتل سے بھی بڑا (گناہ) ہے.اور یہ لوگ اگر ان کی طاقت میں ہو تو تم سے لڑتے ہی حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا١ؕ وَ مَنْ چلے جائیںتاکہ تمہیںتمہارے دین سے پھرا دیں.اور تم میں سے جو (بھی ) يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓىِٕكَ اپنے دین سے پھر جائے.(اور )پھرکفر کی ہی حالت میں مر (بھی) جائے تو( وہ یاد رکھے کہ) ایسے لوگوں کے
Page 304
حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ١ۚ وَ اُولٰٓىِٕكَ اعمال اس دنیا میں(بھی) اور آخرت میں( بھی )اکارت جائیں گے.اور ایسے لوگ دوزخ اَصْحٰبُ النَّارِ١ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۰۰۲۱۸ (کی آگ میں پڑنے )والے ہیں.وہ اس میں (دیر تک )رہیں گے.تفسیر.فرمایا یہ عزّت والے مہینوں یعنی محرم، رجب، ذیقعدہ اور ذوالحج کے متعلق تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آیا ان میں لڑائی کرنا جائز ہے؟ یہ سوال کس طرح پیدا ہوا؟ اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس کے بعد بھی مکہ والوں کے جوشِ غضب میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی بلکہ انہوں نے مدینہ والوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ چونکہ تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے اس لئے اب تمہارے لئے ایک ہی راہ ہے کہ یا تو تم ان سب کو قتل کر دو یا مدینہ سے باہر نکال دو ورنہ ہم خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیںگے اور تم سب کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر قبضہ کر لیں گے اور پھر انہوں نے صرف دھمکیوں پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ان ایام میں یہ کیفیت تھی کہ بسا اوقات آپؐ سار ی ساری رات جاگ کر بسر کرتے تھے.اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہم رات کو ہتھیار باندھ کر سویا کرتے تھے تاکہ رات کی تاریکی میں دشمن کہیں اچانک حملہ نہ کر دے.ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو مدینہ کے قرب و جوار میں بسنے والے قبائل سے معاہدات کرنے شروع کر دیئے اور دوسری طرف ان خبروں کی وجہ سے کہ قریش حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں آپؐ نے ۲ سنہ ہجری میں حضرت عبداللہ بن جحشؓ کو بارہ آدمیوں کے ساتھ نخلہ بھجوایا اور انہیں ایک خط دے کر ارشاد فرمایا کہ اسے دو دن کے بعدکھولا جائے.حضرت عبداللہ بن جحشؓ نے دو دن کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ تم نخلہ میں قیام کرو.اور قریش کے حالات کا پتہ لگا کر ہمیں اطلاع دو.اتفاق ایسا ہوا کہ اس دوران میں قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ جو شام سے تجارت کا مال لے کر واپس آرہا تھا وہاں سے گذرا.حضرت عبداللہ بن جحش ؓ نے ذاتی اجتہاد سے کام لے کر ان پر حملہ کر دیا.جس کے نتیجہ میں کفار میں سے ایک شخص عمروبن الحضرمی مارا گیا اور دو گرفتار ہو ئے.اور مال غنیمت پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا.جب انہوں نے مدینہ میں واپس آکر
Page 305
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپؐ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں لڑائی کی اجازت نہیں دی تھی اور مالِ غنیمت کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا(تاریخ الخمیس زیر عنوان بعث عبداللہ بن جحش الی بنی نخلہ).ابنِ جریرؓ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن جحشؓ اور ان کے ساتھیوں سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا.حالانکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا.وہ خیال کرتے رہے کہ ابھی۳۰ جمادی الثانی ہے.رجب کا آغاز نہیںہوا.بہر حال عمروبن الحضرمی کا ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا جانا تھا کہ مشرکین نے شور مچا نا شروع کر دیا کہ اب مسلمانوں کو ان مقدس مہینوں کی حرمت کا بھی پاس نہیںرہا جن میں ہر قسم کی جنگ بند رہتی تھی(تفسیر ابن جریر زیر آیت ھذا).اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک ان مہینوں میں لڑائی کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے لوگوں کو روکا جائے.اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا جائے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کیا جائے اور اس کے باشندوں کو بغیر کسی جرم کے محض اس لئے کہ وہ خدا ئے واحد پر ایمان لائے تھے اپنے گھروں سے نکال دیا جائے.تمہیں ایک بات کا تو خیال آگیا مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ تم خود کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہو اور خدااور اس کے رسول کا انکار کر کے اور مسجد حرام کی حرمت کو باطل کر کے اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال کر کتنے ناپسندیدہ افعال کے مرتکب ہوئے ہو جب تم خود ان قبیح حرکات کے مرتکب ہو چکے ہو تو تم مسلمانوں پر کس مونہہ سے اعتراض کرتے ہو.ان سے تو صرف نادانستہ طور پر ایک غلطی ہوئی ہے مگر تم تو جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہو.وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ علامہ ابو البقاء کے نزدیک بغیر اعادہ جار کے جر جائز نہیں اس لئے ان کا خیال ہے کہ یہ متعلق ہے فعل محذوف کا اور پورا جملہ یہ ہے وَصَدٌّعَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ(املاء ما مّن بہ الرحمٰن).کشاف نے بھی صَدٌّ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے ہی معنے کئے ہیں.لیکن بعض کے نزدیک اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کا عطف بِہٖ پر ہے اور ضمیر مجرور پر عطف بلا اعادہ جار کے برخلاف قول بصریوں کے جائز ہے.(روح المعانی زیر آیت ھذا) اہل عرب میں اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں.جیسے کہتے ہیں.مَافِیْھَا غَیْرُہٗ وَفَرْسِہٖ.یعنی اس گھر میں اس کے اور اسکے گھوڑے کے سوا اور کوئی نہیں.اس مثال میں فَرْسِہٖ کا عطف ضمیر مجرور پر کیا گیا ہے.پھر فرمایا وَالْفِتْنَۃُ اَکْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے.اس جگہ فتنہ سے وہی فتنہ مراد ہے جس کا لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ میں ذکر آتا ہے.یعنی مسلمانوں کو مرتد کرنے اور انہیں
Page 307
اعمال اس کے کسی کام نہیں آئیں گے کیونکہ اس کا خاتمہ اچھا نہ ہوا.وَ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ اور یہی لوگ دوزخ کی آگ میں پڑنے والے ہوںگے.کیونکہ دنیا میں بھی انہوں نے اپنے ارتداد سے فتنے اور فساد کی آگ کو بھڑکایا تھا.اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اللہ (تعالیٰ) کے راستہ میں جہاد کیاہے اللّٰهِ١ۙ اُولٰٓىِٕكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ١ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰۰۲۱۹ ایسے لوگ یقیناً اللہ (تعالیٰ)کی رحمت کے امید وار ہیں.اور اللہ (تعالیٰ) بہت بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے.تفسیر.چونکہ گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو ارتداد کی حالت میں ہی اس دنیا سے اُٹھ جائیں اور بتایا تھا کہ ایسے لوگوں کی اسلام کو مٹانے کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی.اس لئے اب اللہ تعالیٰ ان کے مقابلہ میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جن کو ارتداد کے بعد توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ پھر اسلام میں داخل ہو جائیں چونکہ ارتداد کا داغ ایک نہایت ہی بدنما داغ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لئے صرف ایمان لانا کافی قرارنہیں دیا بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی توبہ اس وقت قبول ہو گی جب ایمان لانے کے بعدوہ ہجرت اختیار کریں یعنی بزدلی اور اخفائے ایمان جیسی گندی عادتوں کو کلّی طور پر ترک کردیں یا اس علاقہ سے نکل جائیں جہاں دینی معاملات میں جبر سے کام لیا جاتا ہو اور پھر دین کی راہ میں ایک ننگی تلوار بن کر کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مالی اور جانی جہاد کریں.اگر وہ ایسا کریںگے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائیں گے.تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک دفعہ حضرت عمرؓ حج کے لئے مکہ تشریف لے گئے.تو حج کے بعد آپ کی ملاقات کے لئے لوگوں نے آنا شروع کر دیا.انہی ملاقاتیوں میں مکہ کے روساء اور سردار انِ قریش کے بعض لڑکے بھی تھے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بڑی عزّت سے بٹھایا اور ان سے مختلف باتیں پوچھتے رہے اتنے میں ایک غلام صحابی آیا.وہی غلام جو ابتدائے اسلام میں ان روساء عرب اور سرداران قریش کے باپ دادوں کی جوتیاں کھایا کرتے تھے جنہیں وہ گلیوں میں گھسیٹتے اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مار مار کر زخمی کر دیتے تھے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان نوجوانوں سے کہا.ذرا پیچھے ہٹ جائو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
Page 308
صحابی ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے اور صحابی قریب ہو کر حضرت عمرؓ سے باتیں کرنے لگ گئے.اتنے میں ایک اور صحابی آگیا.حضرت عمرؓ نے پھر ان نوجوانوں سے کہا.ذرا پیچھے ہٹ جائو او ران کے لئے جگہ چھوڑ دو.یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں.یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ جوتیوں تک جا پہنچے.یہ دیکھ کر وہ مجلس سے اُٹھ کر باہر آگئے اور ایسی حالت میں آئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے.انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا.کیا کبھی یہ خیال بھی آسکتا تھا کہ ہم کسی زمانہ میں اس قدر ذلیل ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو ہماری جوتیاں اُٹھانا اپنے لئے فخر کا موجب سمجھا کرتے تھے مجلس میں ایک ایک کر کے ہم سے آگے بٹھائے جائیں گے اور ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا جائےگا.یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ہم جوتیوں تک جا پہنچیں گے.گویا وہ جو ذلیل تھے معزز ہو گئے اور ہم جو معزز تھے ذلیل ہو گئے.یہ تمام نوجوان اگرچہ ایماندار تھے مگر غصہ اور جوش میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے لیکن ان میں سے ایک نوجوان جس کا ایمان زیادہ مضبوط تھا وہ کہنے لگا.بھائی! تم نے بات تو ٹھیک کہی مگر اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کردیں؟انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی تھی اس لئے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم مجلس میں پیچھے ہٹا دیئے گئے مگر وہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی.جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنے اموال آپ کی راہ میں قربان کر دیئے تھے ان میں سے گو بہت سے مارے گئے مگر اب بھی جو باقی ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے.اور ان کو ہم سے زیادہ ادب کے مقام پر بٹھایا جائے.انہوں نے کہا یہ بات تو درست ہے مگر کیا اب اس ذلت کو مٹانے کا کوئی ذریعہ نہیں؟ یا کیا کوئی ایسی قربانی نہیں جو اس گناہ کا کفارہ ہو سکے؟ اس پر اسی نے کہا چلو !حضرت عمرؓ کے پاس ہی چلیں اور انہی سے اس کا علاج دریافت کریں.چنانچہ وہ پھر آپ کے مکان پر گئے اور دستک دی مجلس اس وقت تک برخواست ہو چکی تھی.حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اندر بلا لیا اور کہا کس طرح آنا ہوا انہوں نے کہا آج جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں.حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں معذور تھا کیونکہ اس وقت جو لوگ میرے پاس آئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے صحابی تھے اور میرے لئے ضروری تھا کہ میں ا ن کی عزت و تکریم کرتا.انہوں نے کہا ہم اس بات کو خوب سمجھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنے لئے بہت بڑی ذلّت مول لے لی.مگر کیا کوئی ایسا طریق نہیں جس سے یہ ذلّت کا داغ ہماری پیشانیوں سے مٹ سکے؟ حضرت عمررضی اللہ عنہ چونکہ اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جس کا کام اہل عرب کے انساب کو یاد رکھنا تھااور وہ جانتے تھے کہ ان نوجوانوں کے باپ دادا کو کتنی بڑی عزت اور وجاہت حاصل تھی.یہاں تک کہ اسلام کی دشمنی کے زمانہ میں بھی اگر وہ کسی مسلمان کو
Page 309
پناہ دے دیتے تھے تو کسی شخص کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس مسلمان کو دکھ پہنچا سکے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے یہ واقعات آئے اور اس کا تصور کر کے ان پر رقّت طاری ہو گئی اور بات کرنا آپ کے لئے مشکل ہو گیا اور غلبہ رقّت میں آپ نے صرف اپنا ہاتھ اُٹھایا اور شمال کی طرف جہاں شام میں ان دنوں عیسائیوں سے لڑائی ہو رہی تھی اشارہ کر کے کہا کہ اس کا علاج صرف وہاں ہے یعنی اب اس ذلت کا علاج ایک ہی ہے او روہ یہ کہ اس جہاد میں شامل ہو کر اپنی جانیں دے دو.پھر خود بخود لوگ ان باتوں کو بھول جائیں گے.چنانچہ اسی وقت وہ لوگ وہاں سے اُٹھے اور اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے.وہ سات نوجوان تھے جو اس ذلت کو دور کرنے کے لئے جہا د میں شامل ہوئے اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ان نوجوانوں میں سے ایک بھی زندہ مکہ کی طرف واپس نہیں آیا.سب اسی جنگ میں شہید ہو ئے.جس طرح ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر کے رضاء الٰہی حاصل کی تھی.اسی طرح ارتداد کے بعد اسی صورت میں توبہ قبول ہو سکتی ہے.جب زبان سے ایمان کا اظہار کیا جائے اور عمل سے ہجرت اختیار کی جائے.خواہ حقیقی رنگ میں یا معنوی رنگ میں.اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار سے جہاد کیا جائے یہی وہ ذرائع ہیں جن سے وہ رحمت الہٰی کے موردبن سکتے ہیں.يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ١ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وہ تجھ سے شراب اور جُوئے کی بابت پوچھتے ہیں.تو کہہ دے (کہ) ان (کاموں )میں بڑا گناہ (اور نقصان) وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ١ٞ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا١ؕ وَ ہے اور لوگوں کےلئے ان میں (کئی ایک) منفعتیں( بھی) ہیں.اور ان کا گناہ (اور نقصان )ان کے نفع سے بہت يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ١ؕ۬ قُلِ الْعَفْوَ١ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ بڑا ہے.اور وہ (لوگ) تجھ سے (یہ بھی )پوچھتے ہیں کہ وہ (یعنی سائل) کیا خرچ کریں؟ تو کہہ دے کہ جتنا تکلیف لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَۙ۰۰۲۲۰ میں نہ ڈالے.اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچ سے کام لو.حل لغات.اَلْـخَمْرُ اَلْـخَمْرُ اِسْمُ کُلِّ مُسْکِرٍ خَامِرِ الْعَقْلِ(اقرب) خمر ہر ایک نشہ دینے والی چیز کو
Page 310
کہتے ہیں.جو عقل کو ڈھانپ دیتی ہے.اَلْمَیْسِرُ یَسَرَسے مَفْعِلٌ کا صیغہ ہے اور اَلْمَیْسِرُ کے معنے ہیں اَللَّعْبُ بِالْقَدَاحِ (۱)تیروں سے جُوا کھیلنا.(اَوْھُوَ النَّرْدُ اَوْکُلُّ قِمَارٍ) اَوْ ھُوَ الْجُزُوْرُ الَّتِیْ کَانُوْا یَتَقَا مَرُوْنَ عَلَیْھَا (اقرب) (۲) نَرد یعنی شطرنج اور چوپٹ کو بھی میسر کہتے ہیں (۳) ہر قسم کا جُوا بھی میسر کہلاتا ہے.(۴)مَیسر ان اونٹوں کو بھی کہتے ہیں جن پر لاٹری ڈالتے تھے.اَلْاِثْمُ اَلْاَفْعَالُ الْمُبْطِئَۃُ عَنِ الْخَیْرِ(اقرب).وہ کام جو نیکیوں سے روک دیں ان کو اِثْمٌ کہتے ہیں (۲) اِثْمٌ کا لفظ کبھی سزا اور تکلیف اور دکھ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.یعنی اپنے نتیجہ کے اعتبار سے تکلیف وغیرہ کے معنے دیتا ہے.کیونکہ قاعدہ ہے کہ کبھی سبب کو مسبّب کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں.چنانچہ قرآن کریم میں اسے دوسری جگہ ان معنوں میں استعمال کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ١ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا (الفرقان: ۲۹) اس جگہ یَلْقَ اَثَامًا کے یہ معنے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا.اَلْعَفْوَ خِیَارُ الشَّیْءِ وَاَطْیَبُہٗ بہتر سے بہتر اور پاک سے پاک چیز (۲) مَایَفْضُلُ عَنِ النَّفَقَۃِ وَلَا عَسَرَ عَلٰی صَاحِبِہٖ فِیْ اِعْطَا ئِہٖ.جو کسی کے خرچ سے بچ رہے اور دینے والے کو اس کے دینے میں تنگی محسوس نہ ہو.(۳) عَفْوُ الْمَالِ.وہ مال جو بغیر سوال کے دیا جائے.کہتے ہیں اَعْطَیْتُہٗ عَفْوًا یا اَعْطَیْتُہٗ عَفْوَ الْمَالِ.میں نے اُسے بغیر مانگے دیا.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے کہ لوگ تجھ سے شراب اور جُوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہیں یا ناجائز؟ تُو ان سے کہہ دے کہ شراب اور جوئے میں کچھ خرابیاں ہیں اور کچھ فوائد لیکن خرابیاں فوائد کی نسبت زیادہ ہیں.یہ کیا ہی لطیف جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے! ان کے سوال پر انہیں فوری طور پر منع نہیں کیا کہ تم شراب نہ پیو اور جُوا نہ کھیلو.بلکہ فرمایا کہ ان میں فوائد تھوڑےہیں اور نقصانات زیاد ہ.اب تم خود سوچ لو کہ تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اس جواب میں اصولی طور پر خداتعا لیٰ نے ہمارے لئے یہ قاعدہ بیان فرما دیا ہے کہ اگر کسی کام میں فائد ہ زیادہ ہو اور نقصان کم تو اسے اختیار کر لیا کرو.اور اگر نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم تو اسے کبھی اختیار نہ کرو.بالخصوص ایسا کام تو کبھی اختیار نہ کرو جس میں اِثْمٌ کَبِیْرٌ ہو.اِثْمٌ کے معنے گناہ کے بھی ہیں اور اِثْمٌکے معنے نیکیوں سے محرومی کے بھی ہیں.گویا انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجہ میں اسے گناہ ہو.یا جس کے نتیجہ میں وہ نیکیوں سے محروم
Page 311
ہو جائے.خواہ اس میں بظاہر کچھ فوائد بھی دکھائی دیتے ہوں.پھر مَنَافِعُ لِلنَّاسِ فرما کر اسلام نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ خواہ تمہاری نگاہ میں کوئی چیز کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو.تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی خوبیوں سے کلی طور پر انکار نہ کرو.جب شراب اور جُوئے جیسی چیزیں بھی فوائد سے خالی نہیں تو دوسری ضرر رساں چیزوں کو تم فوائد سے خالی کیوں سمجھتے ہو.بے شک تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے ضر ر سے بچو.اور آئندہ نسلوں کو بچائو لیکن تمہاری بینائی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی چیز کا صرف تاریک پہلو ہی دیکھے بلکہ ہر چیز کا تاریک اور روشن دونوں پہلو سامنے رہنے چاہئیں اور حسن کا اقرار کرنے میں تمہیں کبھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے.يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمان اس بارہ میں خود آآکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے حالانکہ عرب کے رہنے والے شراب پینے کے اس قدر عادی تھے کہ وہ اس پر فخر کیا کرتے تھے.چنانچہ ایک عرب شاعر کہتا ہے ؎ اَلَا ھُبِّیْ بِصَحْنِکِ فَاصْبَحِیْنَا فَلَا تُبْقِیْ خُمُوْرَ الْاَنْدَرِ یْنَا (سبع معلّقۃ، معلقۃ عمرو بن کلثوم) یعنی اے میری محبوبہ! تو بیدار ہو.اور اپنے بڑے پیالے میں ہم کو صبوحی پلا.اور اس قدر پلا کہ علاقہ شام کے اندر شہر کے شراب فروشوں کی شراب میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے.سب کی سب ہمیں پلادے.اسی طرح جنگوں کے موقعہ پر وہ خصوصیت سے شراب کا زیادہ استعمال کیا کرتے تھے تاکہ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر لڑیں اور عاقبت اندیشی کا خیال ان میں نہ رہے.مگر ایسے ماحول میں رہنے کے باوجود انہوں نے خود پوچھا کہ یا رسول اللہ! شراب اور جُوئے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ابھی شراب اور جُوئے کی حرمت نازل نہیں ہو ئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ چیزیں قربِ الہٰی میں روک ہیں اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی واضح حکم نازل ہونا چاہیے.پس یہ سوال خود اپنی ذات میں صحابہ کرامؓ کی پاکیزگی ان کی بلندی اخلاق اور ان کے اعلیٰ کردار کا ایک زبردست ثبوت ہے.شراب اور جُوا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کے روکنے کے لئے دنیا میں بڑی بڑی کوششیں ہوتی رہی ہیں.مگر اسلام کے سوا اورکوئی مذہب ان کو روک نہیں سکا.صرف اسلام ہی ہے جسے اس میدان میں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی ہے.چنانچہ شراب
Page 312
کے متعلق اسلامی تعلیم کی حقیقت آشکارا کرنے کے لئے ہم پہلے دیگر مذاہب کی تعلیم کو جو وہ شراب کے متعلق دیتے ہیں بیان کرتے ہیں اور سب سے پہلے اسی مذہب کا ذکر کرتے ہیں جو سب سے قدیم مذہب ہونے کا مدعی ہے یعنی ویدک مذہب، ہندو مذہب کی شراب کے متعلق جو تعلیم ہے اس کے لئے ہمیں زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں اس مذہب کی بنا ویدوںپر ہے اور وید خود اس مسئلہ پر کافی سے زیادہ روشنی ڈالتے ہیں.ویدوں پر خصوصاً رگوید پر جو چاروں ویدوں میں سے اہم ہے ایک اجمالی نظر ڈالنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ شراب نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کا استعمال بعض موقعوں پر ضروری اور موجب ثواب بتایاگیا ہے.اور ہند کے رشی اسے ایک مقدس اور پاک چیز قرار دیتے ہیں.وید کے منتر یکے بعد دیگرے ہماری آنکھوں کے سامنے اس سنجیدہ کوشش کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں جو ہندوستان کا برگزیدہ پجاری اپنے پرماتما کی توجہ کو کھینچنے کے لئے شراب کو پیش کر کے کرتا ہے.اور اگر غور سے دیکھا جائے تو معلو م ہوتا ہے کہ قدیم ہندوستان کے پجاری کی پوجا میں شراب کاد وسری چیزوں کی نسبت بہت زیادہ دخل تھا.وہ سوم کا رس نہ صرف خود پیتا ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت سی پوجا کی چیزوں کو بھی نہلاتا ہے اور اِندر اور دوسرے دیوتائوں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے ان کے سامنے بھی اسے پیش کرتا ہے.اسی طرح اتھروید میں اشونی کمار دیوتائوں کی پوجا کے وقت جو منتر پڑھنے کے لئے بتائے گئے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قدیم ایام کا ہندو پجاری اس چیزکو ایسا متبرک سمجھتا تھا کہ صرف خود ہی شراب کو استعمال نہ کرتا تھا بلکہ اپنے دیوتا سے بھی اس کے استعمال کی درخواست کرتا تھا.چنانچہ کانڈ نمبر۹ ادھیائے نمبر۱ منتر نمبر۱۷ میں لکھا ہے.’’اے اشونی کمارو! پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جنگلی جڑی بوٹیوں میں جو مدھو(شراب) ہے اس وقت (یعنی یگیہ کی تقریب پر) جو کشیدکی جاتی ہے اس کا رس میرے اور آپ کےلئے ہو.‘‘ اس منتر میں تو صرف دیوتا سے شراب کے استعمال کی درخواست ہی کی گئی ہے.مگر بلّور کے بنائے ہوئے نیتر کی پوجا کے وقت اس سے بھی زیادہ یہ کام کیا جاتا ہے کہ اسے شراب سے غسل دیا جاتا ہے.گویا عملاً اسے شراب پلائی جاتی ہے.اور اس کے ساتھ اتھروید کا یہ منتر پڑھا جاتا ہے کہ ’’اے بلّور کے بنائے ہوئے نیتر! آپ ہمارے مہمان ہو کر ہمارے گھر میں رہیئے گا اور ہم آ پ کو گھی شراب شہد اور میٹھے میٹھے اسی طرح کے کھانے دیتے ہیں.آپ ہماری ہمیشہ بھلائی سوچتے رہا کریں.جیسے باپ اپنی اولاد کے لئے بہتری سوچتا رہتا ہے.‘‘ (اتھروید کانڈ نمبر ۱۰ ادھیائے نمبر۶ منتر ۲۶،۲۷)
Page 313
یہ دومنتر تو اس امر پر روشنی ڈالتے ہیں کہ قدیم ہند کا پجاری پوجا کے وقت اپنے دیوتا سے شراب پینے کی درخواست کرتا ہے اور خود شراب پیتا اور بلّور کے نیتر کو شراب میں غوطہ دیتا ہے.مگر اس سے بھی زیادہ وضاحت اسی وید کے کانڈ نمبر۱۰ ادھیائے نمبر۱۰ اور منتر نمبر۱۰ میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوتا خود بھی اپنی کامیابی کی خوشی میں شراب کا استعمال کرتے ہیں چنانچہ لکھا ہے.’’اپنے دشمنوں کو قابو کر کے فتح حاصل کرنے کے لئے اِندر نے شراب کے پیالے پیئے.‘‘ اس زمانہ میں آریہ مت کے بعض ممبروں نے سوم کے رس اور اسی قسم کے اور الفاظ کی تشریح کرتے وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وید میں شراب کا کوئی ذکر نہیں بلکہ گلو وغیرہ کے رس کا ذکر ہے مگر جب ہم تمام کی تمام ہندو قوم کا طریق عمل دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کو مدنظر رکھتے ہیں کہ ہندو قوم کا میل جول کسی ایسی قوم سے جو شراب کی سخت عادی ہو کبھی لمبے عرصے تک اور پورے طور پر نہیں رہا جس سے خیال ہو سکے کہ دوسروں سے یہ عادات انہوں نے اخذ کر لی ہیں تو ہم کو ان تاویلات کے ماننے میں بہت کچھتأ مّل ہوتا ہے.مگر جب ہم اتھرووید کے کانڈ نمبر۱۸ انوواک نمبر۱ سوکت نمبر۱ منتر ۴۸ کو دیکھتے ہیں تو ان تاویلات کا قبول کرنا ہمارے لئے بالکل ناممکن ہو جاتا ہے.کیونکہ اس میں ہم یہ لکھا ہو ا پاتے ہیں کہ.’’ یہ سوم بہت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ ہے اور کچھ میٹھا بھی اور کچھ تیز و تُرش بھی ہے ایسے سوم کو پینے والے اِندر دیوتا کے مقابلہ پر جنگ میں کوئی دشمن نہیں ٹھہر سکتا.‘‘ ان حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہندو مذہب پورے طور پر شراب کے استعمال کی اجازت دیتا ہے.اور بعض عبادات میں اس کا استعمال ضروری قرار دیتا ہے.ہندوئوں کا تمدن بھی اس نتیجہ کی تصدیق کرتا ہے اور ان کی تاریخ بھی اس کی صحت پر شاہد ہے.ایرانی مذہب کی تعلیم.دوسرا قدیم مذہب ایرانیوں کا مذہب ہے.ایرانی قوم ایک مسلسل اورلمبی تاریخ رکھتی ہے بلکہ تازہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تعجب نہیں اس کا تمدن ویدک تمدن سے بھی پرانا ہو.اس قوم کے مذہب قدیم و جدیدسے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں شراب جائز تھی.زردشتی مذہب کی واقفیت رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ زردشت کسی جدید مذہب کا بانی نہ تھا بلکہ اس نے قدیم ایرانی مذہب کو جو مرورزمانہ سے بہت کچھ بگڑ گیا تھا دوبارہ زندہ کیا تھا.پس ایرانی مذہب کا فتویٰ شراب کے متعلق معلوم کرنے کے لئے ہمیں زردشت کی بعثت سے پہلے اور بعد دونوں زمانوں پر نظر ڈالنی چاہیے.گو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی لوگ شراب بکثرت استعمال کرتے
Page 314
تھے مگر مذہبی طور پر وہ اس کو کیسا سمجھتے تھے ؟اس کا پتہ ہمیں زردشتی کتب سے ہی ملتا ہے.چنانچہ پہلوی کتب میں زردشت کی پیدائش کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کے والد یورو شاسپ کو فرشتہ نے ایک شراب کا گلاس دیا جس کے پینے کے قریب زمانہ میں ہی اس کی بیوی دو غدونامی حاملہ ہوئی اور ایک ایسا لڑکا جنی جس نے مشرقی تاریخ میں ایک نیا انقلاب پیدا کرنا تھا.ایک مقدس انسان کی پیدائش کے لئے فرشتہ کا شراب کا گلاس ان کے والد کو پلانا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زردشت کے زمانہ سے پہلے بھی شراب کا استعمال مذہباً نہ صرف جائز بلکہ مستحسن تھا.زردشت نے ایرانی مذہب میں جو اصلاح کی اس کی رو سے بھی شراب کا استعمال ایک مستحسن امر قرار دیا گیا.چنانچہ افرنجن کی دعا ئیںجو زردشتی مذہب کے پادریوں کے پڑھے جانے کے لئے مخصوص ہیں ان کے پڑھے جانے کے وقت جو رسوم ادا کی جاتی ہیں ان میں بھی شراب کا دخل ہے.دستور: ان دعائوں کے پڑھنے کے وقت ایک قالین پر جسے زمین پر بچھایا ہوا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے دھات کی تھالی یا کسی پودہ کے پتہ پر اس موسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ میوہ جات اور پھول رکھے جاتے ہیں اور ساتھ ہی برتنوں میں تازہ دودھ اور شراب اور تازہ پانی اور شربت پڑا ہوتا ہے.غرض ایرانی مذاہب کے مطابق بھی شراب کا استعمال ایک مستحسن اور پسندیدہ فعل قرار دیا گیا ہے.اور بعض مذہبی رسوم کی ادائیگی کے وقت شراب کا استعمال یا اس کا پاس رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے.شراب اور بائیبل.تیسرا قدیم مذہب اسرائیلی مذہب ہے.یہ مذہب بھی ہندو مذہب اور زردشتی مذہب کی طرح اپنا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے شروع کرتا ہے گو اس مذہب کی بنیاد حضرت موسیٰ ؑ نے رکھی ہے.مگر یہ ایک مسلسل سلسلہ تاریخ کے ذریعہ ابو البشر آدم علیہ السلام سے اپنا تعلق جا ملاتا ہے.اس مذہب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شراب کا استعمال ابتدا ئے آفرینش سے برابر چلا آیا ہے اور نہ صرف یہ کہ اسے کبھی بُرا نہیں سمجھا گیا بلکہ خود انبیاء علیہم السلام بھی اسے استعمال کرتے رہے ہیں.بائیبل کی کتاب پیدائش باب۹ آیت ۲۰ تا۲۳ میں لکھا ہے.’’اور نوح کھیتی باڑی کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا.اور اس کی مے پی کر نشہ میں آیا.اور اپنے ڈیرے کے اندر آپ کو ننگا کیا اور کنعان کے باپ حام نے اپنے باپ کو ننگا دیکھا.اور اپنے دو بھائیوں کو جو باہر تھے خبر دی.تب سم اور یافث نے ایک کپڑا لیا اور اپنے دونوں کاندھوں پر دھرا اور پچھلے پائوں جا کر اپنے باپ کی برہنگی کو چھپایا.‘‘
Page 315
یہ توحضرت نوح ؑ کا حال ہے.جو پہلے نبی ہیں جن کی تاریخ ایک حد تک محفوظ ہے.اور جن کے بعد تاریخ ایک حد تک تفصیلی رنگ اختیار کر لیتی ہے.آپ کے بعد دوسرا مہتم بالشان زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے ان کی نسبت ہم بائیبل کے باب۱۴ آیت ۱۸ میں پڑھتے ہیں کہ ملک صدق سالم کے بادشاہ نے ان کی دعوت میں روٹی اور مے پیش کی تھی.اسی طرح حضرت لوط ؑکی نسبت پیدائش باب۹آیت۳۲ و ۳۵ میں لکھا ہے کہ لوط ؑ کی لڑکیوں نے اپنے باپ کومے پلائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں نہ صرف شراب منع نہ سمجھی جاتی تھی بلکہ ضروریات زندگی میں سے خیال کی جاتی تھی.کیونکہ یہ واقعہ عذاب کے بعد کا ہے.جس وقت کہ حضرت لوط ؑ اپنی دونوں لڑکیوں سمیت جنگل میں ایک غار میں رہتے تھے.اس وقت ان کے پاس شراب کا ہونا ظاہر کرتا ہے کہ بائیبل کے بیان کے مطابق اس وقت کے طرز معاشرت کے ماتحت انہوں نے ان چند ضروری اشیاء میں جو وہ برباد ہونے والی بستی سے لےکر نکلے تھے شراب کا شامل کرنا بھی ضروری خیال کیا تھا.بنو اسرائیل میں نبوت کے منتقل ہونے میں بھی شراب کا بہت کچھ دخل ہے.کیونکہ جیسا کہ بائیبل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے ابتداءً بڑے لڑکے ہی وارث ہو اکرتے تھے اور انہی کی نسل سے شجرہ چلایا جاتا تھا.چنانچہ اس طریق کے مطابق حضرت اسحاق ؑنے بھی اپنے بڑے لڑکے عیسو کو برکت دینی چاہی مگر جیسا کہ پیدائش باب ۲۷ سے معلوم ہوتا ہے حضرت یعقوبؑ کی والدہ نے ان کو کھانا پکا کر دیا.اور انہوں نے لذیذ کھانا کھلا کر اور عمدہ شراب پلا کر (آیت۲۵) اور اپنے آپ کو عیسو ظاہر کر کے ان سے اپنے حق میں دُعا کروالی.اور اس طرح نبوت عیسُو کے خاندان سے نکل کر یعقوب یعنی اسرائیل کے خاندان میں آگئی.پس بنی اسرائیلی اپنی روحانی ترقیات میں ایک حد تک مے کے بھی ممنون ہیں.پھر نہ صرف یہ کہ بائیبل کے بیان کے مطابق حضرت اسحاق ؑ نے خود ہی مے پی.بلکہ حضرت یعقوبؑ کے حق میں بھی جن کو وہ اپنا بڑا لڑکا عیسو خیال کررہے تھے یہ دعا کی کہ خداتجھے اناج اور مے کی زیادتی بخشے(آیت ۲۸) جس کے ذریعے انہوں نے بنی اسرائیل کے لئے ہمیشہ شراب کا استعمال ضروری قرار دےدیا کیونکہ اگر وہ شراب کا استعمال ترک کر دیں تو یہ دعا باطل جاتی ہے.حضرت اسحاق ؑکی اس دعا کو حضرت یعقوب ؑ نےبھی اپنی وفات کے وقت کی دعا سے اور تقویت دے دی کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے یہودا اور اس کی اولاد کے حق میں خبر دی ہے.کہ ان کی آنکھیں شراب کے نشہ سے سُرخ رہیں گی.(پیدائش باب۴۹آیت۱۲) اس زمانہ کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے بڑا اور اہم زمانہ حضرت موسیٰ ؑ کا ہے.حضرت موسیٰ ؑ یہودی مذہب کے بانی ہیں.اور اپنے سے پہلے سب شریعتوں کے ناسخ ہیں.مگر جہاں انہوں نے ایسے بہت سے قانون اور رواج جو ان سے پہلے
Page 316
بنی اسرائیل میں رائج تھے موقوف کئے ہیں.شراب کے متعلق پہلے حکم کو تبدیل نہیں کیا بلکہ انہوںنے بھی شراب کو خداوند کا چڑھاو اقرار دے کراس کو مقدس کہا ہے.کیونکہ جیسا کہ گنتی باب۱۸ آیت۱۲ سے معلوم ہوتا ہے اچھی سے اچھی شراب کا حضرت ہارونؑ اور ان کی اولاد کے لئے جن کو کہانت کا عہدہ سپر د کیا گیا تھا وعدہ کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ عمدہ شرابیں خدا تعالیٰ کے نام پر معبد پر چڑھائیں جنہیں کاہن استعمال کریں.یہ وعدے جو اوپر بیان ہوئے ہیں صرف حضرت ہارون ؑاور ان کی اولاد کے لئے ہیں.مگر دوسرے بنی اسرائیل کو بھی خالی نہیں چھوڑا.بلکہ ان کے لئے بھی حضرت موسیٰ ؑ سے خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کریں گے اور شریعت کی پابندی کریں گے تو ان کے رحم کے پھل اور ان کی زمین کے پھل اور ان کے غلّہ اور ان کی مے اور ان کے تیل اور ان کی گائیوں کی بڑھتی اور ان کی بھیڑوں کے گلوں میں اس زمین پر جس کی بابت اس نے ان کے باپ دادوں سے قسم کر کے کہا کہ تجھ کو دوںگا برکت بخشے گا.(استثنا باب۷آیت ۱۳) اس حوالہ کے علاوہ تورات میں اور بھی کئی جگہ بنی ا سرائیل کے لئے شراب کی کثرت کا وعدہ کیا گیا ہے اور حضرت مسیح کی آمد تک جس قدر انبیاء اور سلاطین گذرے ہیں عموماً سب کے ذکروں میں شراب کا بیان ہے گویا ان کی تمام تاریخ سے شراب کا استعمال نہایت کثرت سے ثابت ہوتا ہے.حضرت موسیٰ ؑ کے بعد مذہبی دنیا میں عظیم الشان تبدیلی کر دینے والی ہستی جس کے بعد نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی تغیر عظیم پیدا کرنےو الا انسان مبعوث نہیں ہوا حضرت مسیح ہیں.اس وقت ان کے ماننے والوں کو دنیا میں ایک خاص مرتبہ اور عزت حاصل ہے.اور ان کی تعلیم کووہ نہایت کامل اور مکمل ظاہر کرتے ہیں.انہوں نے بھی شراب کے متعلق جو کچھ فتویٰ دیا ہے وہ اس کی تقدیس کا ہی ہے.انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح شراب کو بُرا نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ معجزانہ طور پر شراب بنا کر لوگوں کو پلاتے تھے.حضرت مسیح کا خود شراب استعمال کرنا تو متی باب ۲۶ آیت۲۹ سے ثابت ہے جہاں لکھا ہے کہ مسیح نے حواریوں سے کہا کہ ’’میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کے پھل کا رس پھر نہ پیوںگا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہت میں نیا نہ پیوں.‘‘ اور ان کامعجزانہ طور پر شراب بنانا او ردوسروں کو پلانا یوحنا باب۲ آیت۳ تا ۱۰ سے ثابت ہوتا ہے.ان آیات کا مضمون یہ ہے.
Page 317
’’ اور جب مے گھٹ گئی.یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس مے نہ رہی.یسوع نے اس سے کہا.کہ اے عورت! مجھے تجھ سے کیا کام میرا وقت ہنوز نہیں آیا.اس کی ماں نے خادموں کو کہا.جو کچھ وہ تمہیں کہے سو کرو.اوروہاں پتھر کے چھ مٹکے طہارت کے لئے یہودیوں کے دستور کے مطابق دھرے تھےا ور ہرایک میں دو یا تین من کی سمائی تھی.یسوع نے انہیں کہا.مٹکوں میں پانی بھرو.سو انہوں نے ان کو لبالب بھرا پھر اس نے انہیں کہا کہ اب نکالو.اور مجلس کے سردار پاس لے جائو.اور وے لے گئے جب میر مجلس نے وہ پانی جو مے بن گیا تھا چکھا اور نہیں جانا کہ یہ کہاں سے تھا مگر چاکر کہ جنہوں نے وہ پانی نکالا تھا جانتے تھے تومیر مجلس نے دولہا کو بلایا اور اسے کہا کہ ہر شخص پہلے اچھی مے خرچ کرتا ہے اور ناقص اس وقت کہ جب پی کے چھک گئے.پر تونے تو اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے.‘‘ مذکورہ بالاحوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائے عالم سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تمام کے تمام مذاہب شراب کے جواز کا فتویٰ دیتے چلے آئے ہیں بلکہ اس کا استعمال بعض مذہبی رسوم میں بھی واجب رکھاجاتا رہا ہے اور اسے متبرک اور مفید شے قرار دیا جاتا رہا ہے.ان مذاہب کی موجودگی اور ان کے رسوخ کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے ان تمام مذاہب کی تعلیم کے خلاف اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اپنے پیروئوں کو سنایا کہ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ١ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ١ٞ وَ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.یعنی لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جُوئے کے متعلق کیا حکم ہے ؟ تُو کہہ دے کہ ان میں نقصان بھی بہت ہے اور لوگوں کے لئے منافع بھی ہیں اور ان کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ ہے.قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں شراب کو منع کیا گیا ہے جیسا کہ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ١ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ احْذَرُوْا١ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ.(المائدة:۹۱ تا۹۳) یعنی اے مومنو! شراب اور جُوا اور چڑھاوے کی جگہیں اور لاٹری شیطانی کاموں میں سے ہیں.سو ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جائو.شیطان سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ تمہارے درمیان شراب اور جُوئے کے ذریعے عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے تم کو روک دے.
Page 318
پس کیا تم باز رہو گے.اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ہمیشہ چوکس رہو.اور اگر تم باوجود سمجھانے کے پھر جائو تو خوب یاد رکھو کہ ہمارے رسول کا فرض صرف یہی ہے کہ تم لوگوں تک حق کو پہنچا دے.ان آیات میں شراب کو قطعی طور پر منع کر دیا گیا ہے اور ایک مسلمان کے لئے اس چیز کا استعمال ہر گز جائز نہیں.میں بتا چکا ہوں کہ جس وقت یہ حکم اسلام نے دیا ہے اس وقت تک تمام مذاہب شراب کو نہ صرف یہ کہ برا نہیں قرار دیتے تھے بلکہ اس کے استعمال کو بالعموم اچھا سمجھتے تھے اور بعض مذاہب کی رسوم میں اس کا استعمال واجب تھا.ایسے موقعہ پر اسلام کا شراب کو منع فرمانا کوئی معمولی بات نہ تھی دنیا اس حکم کی خوبی کو سمجھنے کے لئے ابھی تیار نہ تھی بلکہ اس زمانہ کی طب بھی شراب کو ایک نہایت ہی مقوی اور اعلیٰ درجہ کی شے قرارد یتی تھی اور اس کا پینا صحتِ جسمانی کے لئے نہایت مفید قرار دیا جاتا تھا مگر باوجود ان سب باتوں کے اسلام نے شراب کو منع فرمایا.اور قطعی طور پر اس کا استعمال ناجائز قرار دے دیا اور یونہی بلا وجہ نہیں بلکہ دلائل کے ساتھ اور دلائل دیتے وقت بھی تعصب سے کام نہیں لیا بلکہ اس کے استعمال کو منع کرتے وقت یہ بھی اقرار کیا کہ اس میں فوائد بھی ہیں.ممکن ہے بعض فلسفیوں نے اس کے استعمال کو بعض حالات میں ناپسند کیا ہو لیکن جس رنگ میں اسلام نے اس مسئلہ کو حل کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا.مثلاً جینی مت جو درحقیقت مذہب نہیں ہے بلکہ ایک فلسفہ ہے اس میں بھی شراب کی ممانعت کا کچھ پتہ چلتا ہے.مگر کس بنا پر؟ کسی عقلی بنا پر نہیں.کسی علمی بنا پر نہیں.کسی مدلل پیرا یہ میں نہیں بلکہ اس لئے کہ شراب کے تیار کرنے میں بہت سے کیڑوں کی جان جاتی ہے.ا ورچونکہ جان کا ہلاک کرنا جینی اصول کے ماتحت ناجائز ہے اس لئے شراب کا استعمال باکمال پیروئوں کو نہیں کرنا چاہیے.یہ ممانعت درحقیقت نہ تو کلّی ممانعت ہے اور نہ شراب پر بذاتہٖ نظر ڈال کر اور اس بات کو مدنظر رکھ کر کہ شراب کا اثر اس کے استعمال کرنے والوں پر کیا پڑےگا اس کا حکم دیا گیا ہے بلکہ صرف اس لئے کہ شراب کا استعمال جینی فلسفہ کے اس مرکزی اصل کے خلاف تھا کہ جیو ہتیا کسی طرح نہیں ہونی چاہیے.اس کا استعمال ناپسند کیا گیا ہے.غرض اسلام تمام مذاہب میں سے بلکہ تمام تعلیموں میں سے شراب کے منع کرنے اور بادلائل طور پر منع کرنے میں منفرد ہے.اور ایسے وقت میں اس نے شراب سے اپنے پیروئوں کو منع کیا ہے جبکہ لوگ ابھی اس مناعی کے حکم کو پورے طور پر سمجھنے کے بھی قابل نہیں تھے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے صاف بتادیا تھا کہ شراب کے نقصانات اس کے منافع سے زیادہ ہیں.مسلمان اطباء اپنی کتب میں برابر شراب کی تعریفیں اور خوبیاں بیان کرتے رہے اور اس کثرت سے بیان کرتے رہے کہ ان کی کتب کو پڑھ کر حیرت آتی ہے.چنانچہ میں اس جگہ صرف موجز کی کسی قدر عبارت مختصراً بیان کر دیتا ہوں جو ایک عام
Page 319
درسی کتاب ہے.اس کتاب کا مسلمان مصنف شراب کے وصف کو یوں بیان کرتا ہے.’’اور چاہیے کہ مجلس شراب کے اردگرد منظر لذیذ ہو.پھول ہوں.پیارے دوست ہوں عمدہ خوشبو ئیں ہوں.دل خوش کن راگ ہو اور ہرغم پہنچانے والی اور دل کو تنگ کرنےوالی چیز کو دور کر دینا چاہیے.مثلاً بغل کی بُو، بوسیدہ لباس، غم و غصہ اور شراب نہا کر اور عمدہ کپڑے پہن کر اور سراور داڑھی کے بال کھلے چھوڑ کر اور ناخن کٹوا کر پینی چاہیے.اور یہ بھی چاہیے کہ جس مقام پر شراب پی جائے وہ ہوادار اور کھلا ہو.اور جاری پانی کے کنارے پر ہو.اور اس وقت لطیفہ گو دوست ساتھ ہوں کیونکہ شراب نفسانی قوتوں کو تحریک کرتی ہے اور تمام شہوات کو اُبھارتی ہے پس جب کوئی قوت اپنے مطلب کو نہیں پاتی توتکلیف محسوس کرتی ہے اور منقبض ہو جاتی ہے پس نفس شراب کی طرف پورے شوق سے راغب نہیں ہوتا.اور نہ پورے طور پر اسے ہضم کرتا ہے.پس شراب کا نفع کم ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات شراب کا پینا بیکار جاتا ہے اور شراب پینے سے نفع کی نسبت نقصان زیادہ ہو جاتا ہے.‘‘ شراب کی نسبت یہ رائے ساتویں صدی ہجری کے ایک مصری مسلمان مصنف کی ہے اور اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ باوجود سات سو سال کی علمی ترقی کے مسلمان بھی شراب کی مضرت کو علمی طور پر سمجھنے سے قاصر رہے ہیں.اور اس وقت تک کی تحقیقات سے مجبور ہو کر لکھتے رہے ہیں کہ شراب کا نفع اس کی مضرتوں سے زیادہ ہے حالانکہ قرآن شریف صاف فرما چکا تھا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے.غرض قرآن کریم نے آج سے تیرہ سو سال پہلے جو تعلیم شراب کے متعلق تمام مذاہب کے برخلاف دی تھی اور جس طرح دی تھی وہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی تھی حتّٰی کہ باوجود قرآن کریم کے بیان کے خود مسلمان اطباء علمی طور پر شراب کی مضرت کو ثابت نہیں کر سکے اور ان کو مجبوراً اس امر کا اقرار کرنا پڑا کہ شراب ایک نہایت ہی نفع رساں شے ہے.زمانہ پر زمانہ گذرتا گیا اور صدی کے بعد صدی آتی گئی مگر شراب کے متعلق وہی تحقیق رہی جو ہزاروں سال سے چلی آتی تھی کہ شراب ایک عمدہ شے ہے.بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس تحقیق کی اور بھی تصدیق ہوتی گئی اور اگر کسی علم کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام کی تکذیب کر سکے تو کہا جا سکتا ہے کہ علم طب نہایت دلیری سے قرآن کریم کے اس ارشاد کی تکذیب صدیوں تک کرتا رہا.یونانی طب کے دور ختم ہونے اور طب جدید کے دور کےشروع ہونے پر اور ہزاروں تحقیقاتوں کو تو ردی کر کے پھینک دیا گیا.لیکن شراب کی خوبیوں کے اظہار پر پہلے سے بھی زیادہ زور دیا جانے لگا.اگر طب قدیم تندرست آدمی کی صحت کے قیام اور کمزور کی طاقت بڑھانے کےلئے
Page 320
شراب کے استعمال کو مفید قرار دیتی تھی تو طب جدید نے بعض خطرناک قسم کے مریضوں کا علاج ہی برانڈی تجویز کیا اور اس کے فوائد پر اس قدر زور دیا جانے لگا کہ کوئی ہسپتال مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا جس میں برانڈی کی چند بوتلیں نہ رکھی گئی ہوں اور شراب کو آبِ حیات قرار دیا جانے لگا.اور بعض لوگ علی الاعلان کہنے لگے کہ جب تک شراب کو اسلام جائز نہ قرار دے دنیا کا اسلام کی طرف جھکنا ناممکن امر ہے.مگر باوجود ان تمام تحقیقاتوں اور طبعی شہادتوں کے قرآن کریم کا یہ فیصلہ روشن حروف میں چمک رہا تھا کہ شراب کی مضر تیں اس کے فوائد سے زیادہ ہیں اور باوجود زمانہ کی ناموافق رائے کے کوئی شخص اس فیصلہ کو بدل نہیں سکتا تھا کیونکہ قرآن کریم خدا کا کلام اور آخری شریعت ہے جس کے بعد کوئی اور شریعت نہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب کی مضرتیں صرف جسم انسانی تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا اثر اخلاق پر بھی پڑتا ہے اور بہت پڑتا ہے جیساکہ خود قرآن کریم نے سورئہ مائدہ میں اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان شراب اور جُوئے کے ذریعے عداوت اور بُغض پید ا کرنا چاہتا ہے مگر کتنے لوگ ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں کے ان اثرات کی طرف جو اخلاق پر ہوتے ہیں توجہ کرنے کے لئے تیار ہوں.اور اس زمانہ میں تو ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ تمدن اور تہذیب کی خرابی اور زوال اور انحطاط کے باعث وہ قوم جو شراب سے مجتنب ہے اپنے اخلاق میں بہت ہی گر گئی تھی.پس مقابلہ کیا جاتا تو کس طرح اور چند مثالوں سے کبھی کوئی مسئلہ پوری طرح صاف نہیں ہو سکتا.جو امر قوموں سے تعلق رکھتا ہو اس کے حل کرنے کے لئے قوموں کی ہی مثالیں درکار ہوتی ہیں اور ان کا بہم پہنچانا ناممکن ہو رہاتھا.پس علمی طور پر علم طب کے ذریعے ہی اس پر روشنی پڑتی تھی اور اس مسئلہ کا پورے طور پر فیصلہ ہو سکتا تھا.قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک لفظ جس قدر معانی پر دلالت کرتا ہے ان تمام معانی کی صداقت خدا تعالیٰ خود ظاہر کرتا ہے اور زور آور نشانوں سے ثابت کرتا ہے ہاں بعض معانی کی صداقت ہمیشہ سے ثابت چلی آتی ہے تاکہ ہر زمانہ کے لوگوں کے لئے وہ حجت ہو اور بعض معانی کی صداقت وہ آہستہ آہستہ مختلف زمانوں میں ثابت کرتا ہے.تا معلوم ہو کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے اور کسی انسان کا اس کی تالیف میں دخل نہیں کیونکہ اس میں وہ باتیں ہیں جو اس زمانہ کے علوم سے تعلق نہیں رکھتیں.شراب کے حکم کے متعلق بھی یہ دونوں پہلو اختیار کئے گئے تھے.اس کی اخلاقی مضرتیں تو ہر زمانہ میں ثابت کی جا سکتی تھیں.گو لوگ اس کی طرف پوری توجہ کریں یا نہ کریں اور گو بعض زمانوں میں بہ نسبت دوسرے زمانوں کے ان کا ثابت کرنا زیادہ مشکل ہو.لیکن شراب پینے کی چیز ہے اور پینے کی چیزوں کا پہلا اثر جسم انسانی پر پڑتا ہے اورا ن اشیاء کے متعلق طبعاً لوگوں کی توجہ بھی
Page 321
ایسے ہی اثرات کے معلوم کرنے کی طرف پھرتی ہے.پس اس حکم کی اہمیت اور خوبی اسی وقت پورے طور پر منکشف ہو سکتی تھی جبکہ اس کے جسمانی اثرات کی مضرتیں بھی روز روشن کی طرح ثابت ہوں اور پھر اس کے نفع سے زیادہ ثابت ہوں.اس اظہار ِ حقیقت کا بھی آخر وقت آگیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض ایسی ایجادوں کی توفیق دی جن کے ذریعہ سے انسان نہایت باریک اعصاب اور ریشوں پر مختلف ادویات اور اغذیہ اور تغیرات موسم اور احساسات کا جو اثر ہوسکتا ہے اسے معلوم کرنے کے قابل ہو گیا.ان ایجادوں نے جہاں اور عظیم الشان تغیرات پیدا کئے وہاں شراب کے متعلق بھی قدیم علمی تحقیقات کی غلطی کو ثابت کر دیا اور اکثر علماء طب کو اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ اس کے ضرر اس کے نفعوں سے زیادہ ہیں اس قدیم اور مستحکم خیال کے بدل دینے کا فخر علم النفس کے ایک ماہر کرپلن کو حاصل ہے جس نے اپنے بعض ہم خیالوںکی مدد سے کوشش کر کے اس امر کو ثابت کر دیا کہ شراب کی چھوٹی سے چھوٹی مقدار کے ایک ہی دفعہ کے استعمال سے بھی انسانی دماغ کے باریک ریشوں اور اعلیٰ درجہ کے علمی مرکزوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے.اسی طرح ہاجؔ نے بھی الکوحل کے اس اثر کے متعلق تجربات کئے جو پٹھوں پر پڑتا ہے.اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ شراب کے استعمال سے برداشت اور ذکاوت اور صبر کی قوتوں کو نہایت سخت نقصان پہنچتا ہے.مسٹر الیگزینڈر برائس ایم.ڈی.ڈی.پی.ایچ جو ماہر علم الاغذیہ ہیں شراب کے متعلق اپنی تحقیقات ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں.’’ اس میں کچھ شبہ اب باقی نہیں رہا کہ شراب درحقیقت ایک نہات سخت زہر ہے جو باریک ریشوں کو تباہ کر دیتا ہے پہلے تو یہ اپنا خواب آور اثر ظاہر کرتا ہے اور آہستہ آہستہ تحلیل کرنا شروع کر دیتا ہے.خصوصاً اعصاب کو سخت نقصان پہنچاتا ہے.درحقیقت اس کا حق نہیں کہ اسے مقوی ادویہ میں شامل کیا جائے کیونکہ یہ صرف ایک ایسی دوائی ہے جو ایک عارضی تحریک کر دیتی ہے مگر اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک ضعف رہتا ہے.قریباً تمام سمجھدار ڈاکٹروں کی رائے اب یہی ہو گئی ہے کہ صحت میں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں.اور اگر بیماری کے علاج میں اس کا فائدہ بالکل مشتبہ نہ سمجھا جائے تو بھی یہ بات تو متحقق ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی جگہ عموماً دوسری ایسی دوائیں استعمال کی جائیں جو اس سے کم ضرر رساں ہیں.‘‘ ان انکشافات کا اثر لازمی طور پر علم طب پر پڑنا تھا اور پڑا.چنانچہ۱۹۰۰ء سے برابر علم طب کے ماہروں کی توجہ اس طرف پھرنی شروع ہو گئی کہ شراب کے استعمال کو کم کیا جائے.چنانچہ ایڈنبرگ کے ایک ہسپتال میں جہاں
Page 322
وَ لَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا رسول آیا جو اس (کتاب) کو جو ان کے پاس ہے سچاکرنے والا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ١ۙۗ كِتٰبَ اللّٰهِ ہےتو ان لوگوں میں سے جنہیں (وہ) کتاب دی گئی تھی ایک فریق نے اللہ کی (تازہ) کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَٞ۰۰۱۰۲ پھینک دیا.گویا کہ وہ (اسے) جانتے ہی نہیں.تفسیر.فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو ایک فریق اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا ہے.اور خدا تعالیٰ کی آواز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا.حالانکہ خدا کا بلاوا کوئی معمولی چیز نہیں.اگر ایک معمولی افسر کا بھی بلاوا آجائے تو بسا اوقات انسان پھولا نہیں سماتا.مگر خدا تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے.حالانکہ اگر دل میں نورِ ایمان ہو تو اس آواز کو سُن کر انسان پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو جانی چاہیے.دنیا کے اعزازاس کے مقابلہ میں کیا چیز ہیں؟ خدا تعالیٰ خود بندوں کو یاد کرتا ہے.اور اپنا نبی اُن میں بھیجتا ہے مگر لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں کہ وہ اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے.حالانکہ اُس آواز پر لبیک کہنا اُن کے لئے فخر کا موجب ہوتا ہے.اِسی طرح یہود کو تو خوشی منانی چاہیے تھی کہ ہماری کتابوں کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے اور یہ نبی اُن کی کتابوں اور بزرگوںکی تصدیق کرتا ہے.مگر وہ قوم جو غلط رویہ اختیار کر چکی ہو وہ ایسا کس طرح کر سکتی ہے؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ سے یہی مراد ہے کہ اِس رسول نے اپنی بعثت کے ساتھ اُن پیشگوئیوں کو پورا کر دیا ہے جو خدا تعالیٰ نے ان کتابوں میں بیان فرمائی تھیں جو یہود کے پاس ہیں.گویا اس رسول کے ذریعہ اسرائیلی نبیوں کی صداقت واضح ہو رہی ہے.پس اس رسول پر ایمان لانا درحقیقت اُن کا اپنے سابق الہامی کلام کی تصدیق کرنا اور اُس کے حکموں کی تعمیل کرنا ہے.اور اگر یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے تو یہ اپنی کتاب اور اپنے نبیوں کی پیشگوئیوں کو جھٹلاتے ہیں.غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مُصَدِّق ہیں موسیٰ ؑکے.مُصّدِق ہیں تورات کے.مُصّدِق ہیں تمام اسرائیلی نبیوں کے مگر ان معنوں میں نہیں کہ تورات اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یا موسیٰ ؑ اور عیسیٰ ؑاور دوسرے نبیوں پر ایمان لانا ہی کافی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں بلکہ وہ صرف
Page 323
کے بلکہ بعض صورتوں میں حکم کے ان مذاہب کے بڑے بڑے آدمیوں نے شراب کی مضرتوں کو دیکھ کر یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ اگر شراب کا استعمال اسی طرح جاری رہا تو ان کی قومیں کیا بلحاظ صحت و تندرستی کے اور کیا بلحاظ اخلاق و آداب کے بہت گر جائیں گی.چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے عالم سے ہی ایسے لوگ ہوتے چلے آئے ہیں جو یہ تحریک کرتے رہے ہیں کہ شراب کا استعمال کم کیا جائے اور اعتدال کو ہر حالت میں مدنظر رکھا جائے.تمام مشرقی ممالک کی تاریخ(اور یہی ممالک پرانے زمانہ میں تہذیب و تمدن کے جھنڈے کوبلند کرنے والے تھے) اس بات پر شاہد ہے کہ قدیم سے قدیم زمانہ سے ہندوستان، ایران، چین.فلسطین.مصر.یونان اور کارتھج کے علماء مذہبی فلاسفر اور مقنّن بدمستی سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں.لیکن ان کی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا یہی کہ اگر بعض آدمیوں نے کچھ مدت کے لئے شراب کا استعمال کم کر دیا تو کچھ عرصہ کے بعد پھر تما م کا تمام ملک اس ’’آب حیات‘‘ سے اپنی روح کو تازہ کرنے کے لئے دوڑپڑا.امریکہ کو ہی دیکھ لو.امریکہ میں شراب نوشی کے انسداد کے لئے حکومت نے کتنی کوششیں کیں.لیکن چونکہ ایمان ان لوگوں کے دلوں میں نہیں تھا بلکہ ممانعتِ شراب کے پیچھے صرف ایک قانون کا م کر رہا تھا اس لئے یہ تحریک ناکام رہی.ہزار ہا موتیں صرف اس وجہ سے واقعہ ہوئیں کہ لوگ شراب پینے کے شوق میں سپرٹ پی لیتے اور سپرٹ میں چونکہ زہر یلی چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے اس لئے کئی اندھے ہو جاتے اور کئی مر جاتے.پھر امریکہ میںنصف سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو باہر سے ناجائز طور پر شرابیں منگواتے اور پیتے.گورنمنٹ کا قانون تھا کہ ڈاکٹر کے سرٹیفیکیٹ کے بغیر کسی شخص کو شراب نہیں مل سکتی اس قانون کی وجہ سے ہزاروں ڈاکٹروں کی آمدنیاں پہلے سے کئی گنا بڑھ گئیں وہ فیس لے کر سرٹیفیکیٹ دے دیتے کہ فلاں شخص کا معدہ کمزور ہےیا اور کوئی ایسی بیماری ہے اسے پینے کےلئے شراب ملنی چاہیے.غرض ہزاروں ڈاکٹروں کا گذارہ محض اسی قسم کے سر ٹیفیکیٹوں پر ہو گیا اور باوجود شراب نوشی کے خلاف قانون بن جانے کے لوگ کئی قسم کے حیلوں سے کوشش کرتے کہ کسی طرح قانون شکنی کریں.غرض کسی ملک میں کسی مدبّر، کسی مقنّن، کسی واعظ اور کسی فلاسفر کی کوشش کا یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ لوگوں نے واقعہ میں شراب کم کر دی ہو.اور وہ اس عہد پر قائم رہے ہوں.اگر ایک جماعت نے اس کا استعمال کم کر دیا تودوسری نے اس کی کسر پوری کر دی.شراب بہر حال اپنے مرکز پر قائم رہی اور اسے کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہلا سکا.اب آئو اور اس کے مقابلہ میںاس تاثیر کو دیکھو جو انسدادِ شراب نوشی کے متعلق اسلام کو حاصل ہے اسلام اس وقت دنیا میں آیا جبکہ علم و سائینس کا رواج دنیا میں بہت کم تھا.یونانی علوم اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچ کر مسیحی پادریوں کی
Page 324
سعی سے گوشہ گمنامی میں جا بیٹھے تھے اور سوائے معدودے چند آدمیوں کے دوسرے لوگ ان سے ناواقف تھے.خصوصاً ایشیائے کوچک پر جس کا ان علوم کی ترقی میں خاص حصہ تھا سخت اندھیراچھا یا ہوا تھا.ہندوستانی فلسفہ بھی تنزل پر تھا.ایران بھی اخلاقی اور علمی طور پر انحطاط کی طرف قدم زن تھا.اور عربوں کی حالت توسخت ناگفتہ بہ تھی.حجازی عربوں میں پڑھنا لکھنا ہی بہت بڑا علم تھا.اور اس فن کے واقف بھی چند آدمیوں سے زیادہ نہ تھے.علم الاخلاق ان کے ہاں وہی تھا جو ان کے شاعروں نے اپنے شعروں میں نظم کیا اور علم طب ان کے ہاں وہی تھا جو ان کی بڑی بوڑھیاں بطور صدری نسخوں کے یکے بعد دیگرے ایک دوسری کو سناتی چلی آئی تھیں.اور وہ علم الاخلاق جس کی طرف ان کے شاعروں نے راہنمائی کی ہے یہی ہے کہ شراب انسان کے اخلاق کو اعلیٰ کرتی ہے اور اسے دلیر اور سخی بناتی ہے اور یہی دو خصائل ہیں جن کی عرب پر واہ کرتا تھا.اس کے نزدیک تمام علم الاخلاق انہیں دو صفات میں مرکوز تھا اور ان کا علمِ طب بھی ان کو یہی ہدایت کرتا تھا کہ ہر مرض کا علاج شراب کا جام ہے پس عرب اپنے علوم کے لحاظ سے شراب سے متنفر نہیں بلکہ اس کا دلدادہ تھا.ہرعرب شراب کا عادی تھا اور عادی بھی ایسا کہ اس کے روز مرہ کے شغلوں میں سے سب سے بڑا شغل ہی شراب نوشی تھا.عرب کے شعروں کو پڑھو شراب کے ذکر سے ان کی کوئی نظم خالی نظر نہیں آتی.عرب کا مشہور شاعر طرفہؔ جو اپنی زبان کی خوبی اورمضامین کی بلندی کی وجہ سے عرب کا دوسرے نمبر کا شاعرسمجھا جاتا ہے لکھتا ہے.؎ وَ اِنْ تَبْغِنِیْ فِیْ حَلْقَۃِ الْقَوْمِ تُلْفِنِیْ وَاِنْ تَقْتَنِصْنِیْ فِی الْحَوَانِیْتِ تَصْتَدِیْ کَرِیْمٌ یُرَوِّیْ نَفْسَہٗ فِیْ حَیَاتِہٖ سَتَعْلَمُ اِنْ مِتْنَا غَدًا اَیُّنَا الْصَّدِیْ (کتاب الشعرو الشعراء لابن قتیبۃ) یعنی اگر تو میری تلاش قوم کی مجلس شوریٰ میں کرے تو تُو مجھے وہاں پائےگا.یعنی میں باوجود نو عمر ہونےکے قوم کا معتمد ہوں(یہ صرف بیس سال کی عمر میں مارا گیا تھا) اور اگر تو مجھے شراب کی دو کانوں پر تلاش کرے تو وہاں بھی مجھے پائے گا.یعنی دو ہی مقام ہیں جہاں میں مل سکتا ہوں اپنی دانائی کی وجہ سے قوم کی مجلس شوریٰ میں مجھے جانا پڑتا ہے اور اپنی شراب نوشی کی وجہ سے شراب خانوں پر میرا پھیرا رہتا ہے.پھر کہتا ہے میں وہ شریف النفس ہوں کہ اپنے نفس کو میں نے اس زندگی میں سیراب کر دیا ہے.اور اگر اے دوستو!ہم مر جائیں تو تم کو بعد مردن معلوم ہو جائےگا کہ کون پیاسا
Page 325
ہے.یعنی میں اس قدر شراب پینے والا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی نشہ میں ہی اٹھوں گا.طرفہؔ کی یہ باتیں باتیں ہی نہیں ہیںبلکہ وہ اس پر عمل پیرا بھی تھا.چنانچہ عرب کے بادشاہ عمر و بن ہند نے جب اس کے بعض اشعار پر جو اس نے بادشاہ کی ہجو میں کہے تھے ناراض ہو کر عین اس کے عنفو انِ شباب میں اس کے قتل کا حکم اپنے والئی بحران کو لکھا اور اس نے طرفہؔ سے دریافت کیا کہ وہ اپنے لئے بہترین طریقہ موت کا چُنے.تو اس نے یہ پسند کیا کہ اس کے پاس بہت سی شراب رکھ دی جائے اور اسی کو پیتے وقت اس کی رگوں کا خون نکال کر اسے قتل کر دیا جائے.اسی طرح عرب کا ایک شاعر ابو محجن ثقفی اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے ؎ اِذَا مِتُّ فَادْفِنِّـیْ اِلٰی اَصْلِ کَرْمَۃٍ تُرَوِّیْ عِظَامِیْ بَعْدَ مَوْتِیْ عُرُوْ قُھَا وَلَا تُدْ فِنِّیْ فِی الْفَلَاۃِ فَاِنَّنِیْ اَخَافُ اِذَا مَامِتُّ اَنْ لَّا اَذُوْقَھَا یعنی جب میں مر جائوں تو مجھے انگور کے درختوں کے پاس دفن کیجئیو تاکہ اس کی جڑیں میری ہڈیوں کو سیراب کرتی رہیں اور مجھے جنگل میں دفن نہ کیجیئو.تا ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد میں شراب سے محروم رہ جائوں.(کتاب الشعر و الشعراء لا بن قتیبۃ) شعراء کے کلام کے علاوہ لغتِ عرب بھی عرب کے شراب پر شیدائی ہونے پر دلالت کرتی ہے.عربی زبان میں شراب کے نام اس کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے.اور کسی زبان میں اس کی مثال نہیں ملتی.تمدن عرب بھی اس بات کا شاہد ہے کہ عرب شراب نوشی میں نہ صرف کامل تھا بلکہ باقی تمام دنیا سے بڑھا ہوا تھا.کیونکہ عرب میں شراب کشید کرنے کا طریق بہت قدیم زمانہ میں دریافت کر لیا گیا تھا.چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹنیکا میں لکھا ہے.’’معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ کے لوگوں کو شراب کے کشید کرنے کا طریق معلوم تھا اور تاریکی کے زمانوں میں عرب لوگ شراب کے کشید کرنے کا کام کیا کرتے تھے.‘‘ (انسائیکلوپیڈیابرٹنیکا زیر لفظ (wine اس تاریخی شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب قدیم زمانہ میں شراب بنانے اور اس کے استعمال کرنے میں سب سے آگے تھے.بلکہ وہ دنیا کے لئے کشید کردہ شراب کی جو خمیر سے تیار کردہ شراب سے زیادہ سخت اور زیادہ عادی بنا
Page 326
دینے والی ہے اکیلی منڈی بنا ہوا تھا.یہ ملک تھا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم مبعوث ہوئے اور یہ قوم تھی جس سے شراب چھڑانے کا انہوں نے ارادہ کیا.اس ارادہ کے پورا کرنے کےلئے انہوں نے کیا تدابیر اختیار کیں.اور ان کا کیا نتیجہ نکلا؟ یہ ایک حیرت انگیز تاریخی واقعہ ہے جس پر تمام عقلیں دنگ ہیں اور کل دانا انگشت بدنداں.اس شراب کے نشہ میں مخمور رہنے والی قوم اور شراب کو اپنا ایک ہی دل لگی کا ذریعہ سمجھنے والی جماعت میں ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں.اور مختصر اور صاف لفظوں میں خدا تعالیٰ کا یہ حکم سنا دیتے ہیں کہ شراب کے نقصانات چونکہ اس کے نفع سے زیادہ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لئے اس کو حرام کر دیا ہے پس ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے اور اس کا بنانا.بیچنا.پینا اور پلانا ترک کر دے.اور اس حکم کو سن کر وہ شراب کے شیدائی اپنا سر نیچا کر لیتے ہیں.اور ایک شخص کے منہ سے بھی اس کے خلاف آواز نہیں نکلتی.ہر ایک ان میں سے شرح صدر سے اس حکم کو قبول کر لیتا ہے اور اس وقت کے بعد شراب کا گلاس کسی ایک فرد کے منہ کے قریب بھی نہیں جاتا.وہ لوگ مہلت نہیں مانگتے قلّت و کثرت کا سوال نہیں اٹھاتے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس چیز کی زیادتی حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے.ان میں لیکچروں کی ضرورت پیش نہیں آتی.شراب کی بُرائیاں ذہن نشین کرنے کی حاجت نہیں ہوتی.کیونکہ اسلام نے ان کے ذہنوں کو ایسی جلا دے دی تھی کہ حق بات کی طرف توجہ دلانا ان کے لئے کافی ہوتا تھا.اور تعصب اور خودبینی سے ان کو اس قدر دور کر دیا تھا کہ اپنی غلطیاں خودبخود ان کی آنکھوں کے سامنے آجاتی تھیں.پس کسی لیکچرار کے لیکچر یا میجک لنٹرن کی تصاویر کی ان کو ضرورت نہ تھی.ان کے لئے صرف ایک اشارہ کافی تھا.ایک لفظ بس تھا.اور سب معاملہ آپ ہی آپ ان کے لئے واضح ہو گیا.ان کا اپنا نفس ان کے لئے لیکچرار تھا اور گوشہ ہائے دماغ میجک لنٹرن کے پردے جن پر وہ عقل کی آنکھوں کے ساتھ خوب اچھی طرح ان بدمستیوں کے نظاروں کو دیکھ سکتے تھے جو شراب نوشی کے نتیجہ میں ظاہر ہوتے ہیں وہ جھوٹی تصویروں کے محتاج نہ تھے سچا نقشہ ان کی رہنمائی کے لئے کافی تھا.اسلام کے اس دوحرفہ حکم کا جو اثر شراب نوشی پر ہوا اس کی بہترین مثال ذیل کا واقعہ ہے جو مسلم.مسند احمد بن حنبل اور ابن جریر کی روایات سے ماخوذ ہے.حضرت انس ؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے تھے اور مدینہ کے رہنے والے تھے.بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ابوطلحہ کے مکان پر مجلس شراب لگی ہوئی تھی اور بہت سے دوست جمع تھے.میں شراب پلا رہاتھا.دور پر دور چل رہا تھا اور نشہ کی وجہ سے ان کے سر جھکنے لگے تھے کہ اتنے میں گلی میں کسی نے آواز دی
Page 327
کہ شراب حرام کی گئی ہے.بعض لوگوں نے کہا کہ اُٹھ کر دریافت کرو کہ یہ بات درست بھی ہے یا نہیں؟ مگر بعض دوسروں نے کہاکہ نہیں پہلے شراب بہا دو پھر دیکھا جائے گا.اور مجھے حکم دیا کہ میں شراب کابرتن توڑ کر شراب بہادوں چنانچہ میں نے ایک سونٹا مار کر وہ گھڑا جس میں شراب تھی توڑ دیا اور اس کے بعد وہ لوگ کبھی شراب کے نزدیک نہیں گئے.(صحیح مسلم کتاب الاشربۃ باب تحریم الخمر،مسند احمد بن حنبلروایت حضرت انس ؓ، تفسیر طبری زیر آیت ھٰذا) اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کااثر لوگوں کے دلوں پر کیا تھا.مجلس شراب میں جبکہ لوگ نشہ میں ہیں.ایک شخص کے خبر دینے پر بلا تحقیق شراب کا بہا دینا کوئی معمولی بات نہیں.اس کی اہمیت کو وہ اقوام زیادہ سمجھ سکتی ہیں جو شراب کی عادی ہیں.کیونکہ جب دور سے دیکھنے والے ان کی اس حالت کو عجیب حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو خود ان کے دل ضرور اس حالت کی خصوصیت کو اچھی طرح محسوس کرتے ہوںگے.اس واقعہ کو دوسرے مذاہب اور دوسرے تمدنوں اور قوانین کے اثرات کے ساتھ ملا کر دیکھو کہ کیا دونوں میں زمین وآسمان کا فرق نہیں؟ آج جبکہ سائینس اور علومِ طبعیہ شراب کی مضرت کو ثابت کر رہے ہیں اور شراب کے ترک کرنے میں ملکی بہبودی اور مالی فراخی کی بھی امید ہے پھر بھی لوگ شراب چھوڑنے کے لئے تیار نہیں لیکن عرب کا مخمور مسلم ایک راستہ پر چلنے والے کی اکیلی آواز سن کر کہ شراب حرام کی گئی ہے شراب کے مٹکوں کو توڑ کر مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی کا دریا بہا دیتا ہے.اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍوَ بَارِکْ وَسَلِّمْ.اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ.دوسر ی چیز جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے وہ جُوا ہے.جوا بھی اہل عرب کی گھٹی میں رچا ہوا تھا.چنانچہ انہوں نے جب کوئی بڑی دعوت کرنی ہوتی تو اس کے اخراجات کے لئے یہ انتظا م کرتے کہ تمام امراء مل کر جُوا کھیلتے اور جو ہار جاتا اس پر اس خرچ کی ذمہ واری ڈال دی جاتی.اسی طرح جنگوں کے موقعہ پر وہ قرعہ اندازی سے کام لیتے اور جس امیر آدمی کا نام نکلتا اس کا فرض قرار دیا جاتا کہ وہ لڑنے والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے اور ان کو شراب مہیا کر کے دے.گویا یہ جنگی اخراجات پورا کرنے کا ایک ذریعہ تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مسلمانوں کو منع فرما دیا کیونکہ جس طرح شراب جسم اور اخلاق اور روحانیت کو تباہ کرنے والی چیز ہے اسی طرح جُوا بھی اخلاق اور تمدن کو تباہ کرنے والی چیز ہے.جُوئے کا عادی انسان اگر جیتتا ہے تو اور ہزاروں گھروں کی بربادی کا موجب ہو کر پھر جُوئے باز میں زمین اور روپیہ لٹانے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے.شاید ہی کوئی جوئے باز ایسا ہو گا جو روپیہ کو سنبھال کر رکھتا ہو.بالعموم جُوئے باز بے پرواہی سے اپنے مال کو لٹاتے ہیں اور ایک طرف تو اور لوگوں کو برباد کرتے ہیں
Page 328
اور دوسری طرف اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ روپیہ کمانے میں انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی.پھر جُوا عقل اور فکر کو بھی کمزور کر دیتا ہے.اور جُوئے باز عادتاً ایسی چیزوں کے تباہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جنہیں کوئی دوسرا عقلمند تباہ کرنے کےلئے تیار نہیں ہوتا.يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ.جب شراب سے جو سپاہیوں میں تہور پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تھا اور جوئے سے جو لوٹ مارکا طریق تھا اور جس سے وہ لوگ جنگی اخراجات پورا کیا کرتے تھے.روک دیا گیا توبجائے اس کے کہ ان کے دلوں میں کوئی انقباض پیدا ہوتا انہوں نے قربانیوں کی راہ میں ایک اور قدم آگے بڑھایا.اور جائز ذرائع سے کمائے ہوئے اموال کے متعلق بھی یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ انہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں کس نسبت سے خرچ کرنا چاہیے چونکہ پہلے بھی ایک ایسا ہی سوال گزر چکا ہے اس لئے یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں اقسام صدقہ کے متعلق سوال تھا اور یہاں کمیت کے متعلق سوال ہے یعنی جب جُوا بھی منع کر دیا گیا تو ان کے دلوں میں سوال پیدا ہوا کہ اب لازماً ہمیں زیادہ قربانی کی ضرورت ہو گی.سو ہم کیا خرچ کریں.کیا سب کچھ یا کسی اور نسبت سے ؟گویا جس حد تک ہمیں اپنے اموال خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے چاہئیں اس پر روشنی ڈالی جائے.اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں صرف ایک لفظ عفو استعمال فرمایا ہے جس کے ایک معنے اس مال کے ہیں جو ضروری اخراجات سے بچ جائے اور جس کے دینے سے انسان کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہو.دوسرے معنے عَفْوٌ کے خِیَارُ الشَّیْ ئِ وَاَطْیَبُہٗ کے ہیں.یعنی سب سے اچھی اور پاکیزہ شے اور تیسرے معنے عَفْوٌ کے بغیر مانگے دینے کے ہیں.مفسرین نے اس آیت کے کئی معنے لکھے ہیں ایک تو یہ کہ اس جگہ جہاد میں اموال خرچ کرنے کا حکم ہے.صدقات مراد نہیں گویا ان کے نزدیک زیر تفسیر آیت کے یہ معنے ہیں کہ جب جہاد درپیش ہو تو اپنی ضروریات سے زائد مال تمام کا تمام جہاد کے لئے دے دو.دوسرے معنے اس کے یہ کئے جاتے ہیں کہ یہاں جہاد کا نہیں بلکہ صدقات کا ذکر ہے.اور پھر عَفْوٌ کے لحاظ سے اس کے کئی معنے کرتے ہیں (۱) بعض کہتے ہیں کہ عَفْوٌ کے معنے ضرورت سے زائد مال کے ہیں.چنانچہ ابتدائے اسلام میں سال بھر کے نفقہ سے جو کچھ بچ رہتا اس کے فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا مسلمانوں کو حکم تھا مگر آیت زکوٰۃ کے نازل ہونے پر یہ حکم موقوف ہو گیا.گویا ان کے نزدیک یہ آیت اب منسوخ ہو چکی ہے (۲) دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے متعلق حکم ہے اور مجملاً بیان ہوا ہے اس کی تفصیل دوسری جگہوں سے معلوم ہوتی ہے (۳) ایک اور جماعت عفو کے معنے اس مال کے کرتی ہے جس کا خرچ کرنا بوجھ معلوم نہ ہو.(۴) بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنے درمیانی خرچ کے ہیں یعنی نہ بالکل کم خرچ کرو اور نہ حد سے زیادہ (۵) پھر بعض نے کہا ہے کہ عَفْوٌ کے
Page 329
معنے بہتر اور پاک مال کے ہیں.اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اور پاک مال میں سے خرچ کرو.یہ نہیں کہ پُرانی اشیاء یا دوسروں کے اموال اٹھا کر دے دو.(۶) بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ و خیرات خوب دل کھول کر کرو.جس جماعت نے اس آیت کے یہ معنے کئے ہیں کہ جو ضرورت سے زائد بچے اسے خرچ کرو.اس نے بھی اسے یا تو جہاد پرچسپاں کیا ہے یا منسوخ قرار دیا ہے.اور وہ اس بات پر مجبور بھی تھے کیونکہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے عمل اور اُمتِ اسلامیہ کے طریق کو اس کے خلاف دیکھتے تھے.ا حادیث بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اپنے اخراجات نکال کر باقی سارا مال تقسیم کر دینا اسلامی حکم نہیں.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یَجِیْءُ اَحَدُکُمْ بِمَالِہٖ کُلِّہٖ یَتَصَدَّقُ بِہٖ وَیَجْلِسُ یَتَکَفَّفُ النَّاسَ اِنَّمَا الصَّدَ قَۃُ عَنْ ظَھْرِ غِنًی (البحر المحیط سورۃ البقرۃ زیر آیت ھٰذا ) یعنی تم میں سے بعض لوگ اپنا سارا مال صدقہ کے لئے لے آتے ہیں اور پھر لوگوں کے آگے سوال کےلئے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں.صدقہ صرف زائد مال سے ہوتا ہے.ا سی طرح فرماتے ہیں اِنْ تَذَرَ وَرَثَتَکَ اَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَھُمْ عَالَۃً یَتَکَفَّفُوْنَ النَّاسَ(البحر المحیط زیر آیت ھذا) یعنی اگر تو اپنے ورثاء کو دولت مند چھوڑ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے بہ نسبت اس کے کہ تو ان کو غریب چھوڑ جائے.اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں.اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضر ت سعد بن ابی وقاص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ثلث مال کے تقسیم کر دینے کی اجازت چاہی مگر آپ نے انہیں منع فرمایا.پھر انہوں نے آدھا مال تقسیم کرنا چاہا تو اس سے بھی منع فرمایا پھر انہوں نے تیسرے حصہ کے تقسیم کر دینے کی اجازت چاہی تو اس حصہ کی آپؐ نے اجازت دے دی مگر ساتھ ہی فرمایا اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ کَثِیْرٌ ( ترمذی کتاب الوصایا باب ما جاء فی الوصیۃ فی الثلث)یعنی تیسرے حصہ کی وصیت کر دو گو ثلث بھی کثیر ہے.غرض یہ خیال کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ جو مال ضرورت سے زائد بچے اُسے تقسیم کر دینا چاہیے بالکل خلاف اسلام اور خلاف عمل ِ صحابہؓ ہے جن میں سے بعض کی وفات پر لاکھوںروپیہ ان کے ورثاء میں تقسیم کیا گیا (اُسد الغابۃ، عبد الرحمٰن بن عوفؓ).پھر اگر اسلام کا یہی حکم تھا تو زکوٰۃ کا حکم دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی؟ جب سب مال جو ضرورت سے زائد ہو تقسیم کر دینے کا حکم ہے تو زکوٰۃ مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی.اور پھر ضرورت سے بچے ہوئے کی اصطلاح خود مبہم ہے.بعض لوگ جو کچھ ان کو مل جائے گو لاکھوں روپیہ ہی کیوں نہ ہو خرچ کر دیتے ہیں اور ضرورت سے زائد ان کے خیال میں کوئی مال ہوتا ہی نہیں.پھر بعض لوگ اپنا سب مال تجارت وغیرہ میں لگائے رکھتے ہیں.ان کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ نہیں بچ
Page 330
سکتا.عقلاً بھی یہ خیال بالکل باطل ہے کیونکہ جب تک ایک جماعت ایسے لوگوں کی نہ ہو جو مال دار ہوں عام ملکی ترقی نہیں ہو سکتی اور غرباء کو بھی نقصان پہنچتا ہے.اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض روحانی لوگ اپنے اموال کو حتی الوسع غرباء کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں اور اسے اسلام نے منع نہیں کیا بلکہ پسند کیا ہے مگر یہ بات غلط ہے کہ اسلام نے اس امر کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں مالی مساوات قائم کی جائے.اور ضرورت سے زیادہ مال لوگ لازماً خرچ کر دیا کریں.اگر یہ اصل تسلیم کیا جائے تو یہ اصل بھی مقرر کرنا پڑے گا کہ ضرور ت سے مراد عام حالتِ ملکی کے مطابق اخراجات ہوںگے ورنہ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ ہر شخص اپنی ضرورت کا خود فیصلہ کرے تو پھر بھی مساوات نہیں رہے گی.کوئی شخص اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں اور عمدہ سے عمدہ کپڑوں اور وسیع اور کھلے اور آراستہ و پیراستہ مکانوں اور خوشنما چمنوں اور میوہ دار باغوں کے لئے روپیہ رکھ کر باقی اگر بچے گا تو غربا ء میں بانٹ دے گا.اور غریب بیچارے معمولی لباس پہننے اور جھونپڑیوں میں رہنے پر مجبور ہوں گے.اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے احکام کے مطابق ہر مسلمان حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس کے ملک کے باشندے فاقہ سے نہ رہیں اور ان کے قابلِ ستر مقامات کے لئے کپڑا مہیّا کیا کرے.گویا انسانی زندگی کی پوری طرح حفاظت کر ے.اس کے لئے وہ امراء سے شریعت کے حکم کے مطابق مال لے کر غرباء پر خرچ کرتی ہے اس سے زیادہ جو کچھ خرچ کیا جائے وہ امراء کی اپنی مرضی پر منحصر ہے.ہاں! اگر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کوئی شخص فاقہ سے مرتا ہوا کسی کو نظر آئے تو اس کا فرض ہے کہ اس کی جان بچانےکی پوری کوشش کرے.اس دعویٰ کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کیا ہے.آپؐ نے اسے اسلام کے اصولی احکام بتائے.اور ان میں زکوٰۃ کا مسئلہ بھی بیان فرمایا.یہ سب کچھ سن کر اس شخص نے کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم.اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے اس قول کو پورا کر دیا تو یہ کامیاب ہو گیا(بخاری کتاب الایمان باب الزکٰوة من الاسلام ).اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غرباء کی مدد کے لئے زکوٰۃ سے زیادہ دینا کسی پر فرض نہیں.ہاں اگر کوئی زیادہ دے تو یہ اس کی نیکی ہے.دراصل اس آیت میں تین قسم کے لوگوں کے لئے تین مختلف احکام دیئے گے ہیں.اور یہ تینوں احکام عفو کے لفظ کے اندر شامل ہیں.پہلا حکم جو ادنیٰ درجہ کا ایمان رکھنے والوں کے لئے ہے وہ تو یہ ہے کہ تم اس قدر خرچ کرو کہ بعد میں تمہارے ایمان میں کوئی تزلزل واقع نہ ہو اور تمہارےدین اور ایمان کو کوئی نقصان نہ پہنچے.ہم نے دیکھاہے بعض لوگ جوش میں آکر بہت سا روپیہ دینی ضروریات کے لئے صرف کر دیتے ہیں لیکن بعد میں جب انہیں مالی مشکلات محسوس ہوتی ہیں تو اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں.ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے
Page 331
کہ جس نے کل اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اپنا ہاتھ اتنانہ پھیلائے کہ بعد میں یہ انفاق اس کے لئے ٹھوکر کا موجب بن جائے.دوسرا حکم ان سے اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو یہ دیا کہ تمہارا جو اچھے سے اچھا مال ہے اسے تم خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو.اور (۳) جو لوگ اس سے بھی اوپر درجہ کے ہیں انہیں یہ حکم دیا کہ وہ بغیر کسی کے سوال کے خود ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال دے دیا کریں.گویا ان سے کسی کو مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی چاہیے بلکہ انہیں خودبخود مذہبی اور قومی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے.اور ہمیشہ اس کے لئے اپنے اموال خرچ کرتے رہنا چاہیے.کَذٰلِکَ يُبَيِّنُ اللّٰہُ لَکُمُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُوْنَ فِی الدُّنْیَا و َالْاٰخِرَۃِ.کَذٰلِکَ میں ک واحد کی علامت آیا ہے حالانکہ لَکُمْ بتاتا ہے کہ مخاطب بہت سے ہیں.اس سے معلوم ہوجاتا ہے کہ کسی جگہ قرآن کریم میں واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور مراد جمع ہوتی ہے.ابوحیان کہتے ہیں وَھِیَ لُغَۃُ الْعَرَبِ یُخَاطِبُوْنَ الْـجَمْعِ بِخِطَابِ الْوَاحِدِ (بحرمحیط زیر آیت ھٰذا) یعنی یہ اہل عرب کا محاورہ ہے کہ وہ بعض دفعہ جمع کے لئے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں.جیسے کہتے ہیں قَدْکَثُرَ الدِّرْھَمُ وَالدِّیْنَارُ.اسی طرح کہتے ہیں فَقُلْنَا اَسْلِمُوْا اِنَّا اَخُوْکُمْ ہم نے کہا تم مسلمان ہوجائو ہم تمہارے بھائی ہیں.یعنی اِخْوَانُکُمْ کہنے کی بجائے اَخُوْکُمْ کہہ دیا گیا.اسی طرح کہتے ہیں کُلُوْافِیْ نِصْفِ بَطْنِکُمْ تَعِیْشُوْا تم نصف بھوک رکھ کر کھائو.تم زندہ رہو گے.(الصاحبی لاحمدبن فارس باب الواحد یراد بہ الجمع) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شرعی احکام کا چونکہ ایک اثر دنیوی زندگی پر پڑتا ہے اور ایک اخروی زندگی پر.اس لئے ہم اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ تم ان پر غور کر سکو.اور تم جو بھی قدم اٹھاؤ علیٰ وجہ البصیرت اٹھائو.اندھا دُھند کسی بات کو نہ مانو.لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُوْنَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃٖ کا اشارہ اِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ بے شک شراب اور جُوئے میں بعض قسم کے فوائد بھی ہیںمگر ان میں ضرر زیادہ ہیں.دنیوی نقطہ نگاہ سے بھی اور دینی نقطہ نگاہ سے بھی.اسی طرح دوسرے احکام بھی تمہارے فائدہ کے لئے دیئے گئے ہیں.پس تمہارا کام ہے کہ تم غوروفکر سے کام لے کر وہ راہ اختیار کرو جودینی اور دنیوی دونوں رنگ میں تمہیں کامیابی کی منزل کی طرف لے جانے والی ہو.
Page 332
فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ١ؕ وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ١ؕ قُلْ اس جہان کے بارے میں (بھی) اور آخرت کے بارے میں بھی.اور یہ (لوگ )تجھ سے یتامیٰ کے بارے میں( بھی) اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ١ؕ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ پوچھتے ہیں.تو کہہ دے (کہ) ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے.اور اگر تم ان سے مل جل کررہو تو (اس میں کوئی يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ١ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ١ؕ حرج نہیں کیونکہ) وہ تمہارے بھائی ہی ہیں اور اللہ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلہ میں خوب اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۰۰۲۲۱ جانتا ہے.اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا.اللہ یقیناً غالب (اور) حکمت والا ہے.حلّ لُغات.اَعْنَتَ کے معنے ہیں وہ کام سپرد کرنا جس کی طاقت اور برداشت نہ ہو.کہتے ہیں اَعْنَتَ الرَّاکِبُ الدَّآبَّۃَ اَیْ حَمَلَھَا مَالَا تَحْتَمِلُہٗ (اقرب) سوار نے سواری وغیرہ کو ایسے کام پر لگایا جس کی اسے طاقت نہ تھی.تفسیر.فرماتا ہے لوگ تجھ سے یتامیٰ کے متعلق سوال کرتے ہیں.تو ان سے کہہ دے کہ ان کی اصلاح اور ترقی کو مدنظر رکھنا بڑا اچھا کام ہے اوراگر تم ان سے مل جل کررہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ آخر وہ تمہارے بھائی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر رہنا بڑی اچھی بات ہے.اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلہ میں خوب جانتا ہے.یتامیٰ کے متعلق آج دنیا میں بڑاظلم ہو رہا ہے.یا تو ان پر حد سے زیادہ سختی کی جاتی ہے اور یا پھر حد سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بگڑ جاتے ہیں حالانکہ نہ ان پر زیادہ سختی کرنی چاہیے اور نہ اتنا پیار کرنا چاہیے کہ خواہ وہ کچھ کریں یہ کہہ دیا جائے کہ اسے کچھ نہیں کہنا اس کا باپ مرا ہوا ہے.عام طور پر لوگ ان کو لاوارث پا کر یا تو حد سے زیادہ سختی کرتے ہیں یا پھر حد سے زیادہ نرمی.لوگ جھوٹے رحم سے کام لے کر انہیں کچھ نہیں کہتے اور اس طرح وہ بچے جو یتیم رہ جاتے ہیں بگڑ جاتے اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے.قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ہر بات میں ان کی
Page 333
اصلاح کو مدنظر رکھو اور درمیانی راہ اختیار کرو.قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ یتامیٰ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی طرف توجہ نہیں کرتے انہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ خود مر جائیں اور اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ جائیں؟(النّساء: ۱۰) اس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یتامیٰ کی پرورش اور ان کی نگہداشت ایک اہم ترین فرض ہے لوگ اگر مرنے سے ڈرتے ہیں تو محض اس وجہ سے کہ وہ دیکھتے ہیں فلاں شخص مر گیا اور اس کے بچے دربدر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں یا ان بچوں کو کسی نے ملازم رکھ لیا ہے تو وہ بات بات پر ان کو بوٹ سے ٹھوکریں مارتا اور ان کے مونہہ پر تھپڑ رسید کرتا ہے وہ روتے ہیں چیختے ہیں چلاتے ہیں مگر ان کی آہ وزاری اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی.یہ حالات دیکھ کر وہ بھی موت سے گھبراتا ہے اورسمجھتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی سلوک کریںگے.لیکن اگر قومی کیریکٹر ایسا اعلیٰ درجہ کا بن جائے کہ جب کوئی شخص مرے تو اس کے بچوں کے متعلق ساری قوم میں ایک زبردست جذبہ اخوت پیدا ہو جائے اور ہر شخص کہے کہ ان بچوں کو میرے سپرد کیا جائے میں اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کروں گا تو موت کا ڈر ہر شخص کے دل سے نکل جائے اور وہ سمجھنے لگ جائے کہ اگر میں مر گیا تب بھی میری قوم کے افراد ایسے اچھے ہیں کہ وہ میرے بچوں کی میری طرح ہی خبر گیری کریں گے اور انہیں تھپڑوں اور بوٹ کی ٹھوکروں کا نشانہ نہیں بنائیں گے.پس یتامیٰ کی خبر گیری اور بیوائوں سے حسنِ سلوک یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو قوم میں جرأت اور بہادری پیدا کردیتی ہیں.اگر یہ چیز قوم میں موجود نہ ہو بلکہ اس کے برعکس اس کے افراد کا نمونہ یہ ہو کہ وہ یتامیٰ تو رکھتے ہوں مگر ملازم بنا کر بلکہ ملازموں سے بھی بدترحالت میں اور وہ ذرا ذرا سی بات پر ان کو تھپڑ مارنے کے لئے تیار ہو جاتے ہوں تو کون شخص ہے جس کا مرنے کو دل چاہے گا؟ ہر شخص ڈرے گا ہرشخص موت سے گھبرائے گااور سمجھے گا کہ میری موت میرے بچوں کی موت ہے.میر ی موت میری بیوی کی موت ہے.میں مروں تو کس طرح اور جان دوں تو کیوں ؟پس ضروری ہے کہ ساری قوم کا یہ کیریکٹر بن جائے کہ جب کوئی شخص فوت ہو تو یہ سوال نہ ہو کہ کون اس کے بچوں کی پرورش کرےگا بلکہ لوگ خود دوڑتے ہوئے جائیں اور ان بچوں کو اپنے سینہ سے لگاتے ہوئے اپنے گھروں میں لے آئیں اورا پنے بچوں کی طرح بلکہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر ان سے محبت اور پیار اور نرمی اور شفقت کا سلوک کریں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے ایک بچہ یتیم رہ گیا تو بعض صحابہؓ میں آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ایک کہتا میں اس کی پرورش کروں گا.دوسراکہتا ہے میںاس کی پرورش کروں گا.آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ بچہ سامنے کرو او ر وہ جس کو پسند کرے اس کے سپر د کر دو.مگر آج یہ
Page 334
حالت ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے لگتا ہے تو اسے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں سب سے بڑا فکر اور اضطراب یہی ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا.کون ان کی پرورش کرے گا.کون ان کی نگہداشت کرےگا کون ان کی طر ف محبت اور پیا ر کی نگاہ سے دیکھے گا؟؟ اور جب وہ شخص مر جاتا ہے اور اس کے بچوں کی پرورش کا سوال سامنے آتا ہے تو ایک شخص کہتا ہے میرا دل تو چاہتا ہے کہ بچہ لے لوں مگر کیا کروں مجھ پر بوجھ بڑا ہے.دوسراکہتا ہے منشاء تو میرا بھی یہی تھا مگر مشکلات بہت ہیں.تیسرا کہتا ہے میں بھی یہ ثواب حاصل کرنا چاہتا تھا مگر بہت مجبوری ہے.اس طرح ایک ایک کر کے ہر شخص اس بوجھ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صحابہؓ میں یہ بات نہیں تھی وہ بھاگتے نہیں تھے بلکہ خوشی سے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے.جب کسی قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ یتامیٰ و مساکین کی خبر گیری کرنے لگ جائے ان کا احترام افراد قوم کے دلوں میں پیدا ہو جائے.ان کی پرورش میں انہیں سکون اور راحت حاصل ہو اور وہ یتیموں کو ایسا ہی سمجھیں جیسے ان کے اپنے بچے ہیں تواس وقت ایمان کے بغیر بھی وہ قوم بہادر بن جاتی ہے اور جب اس کے ساتھ کسی کو حیات بعد الموت پر ایمان بھی ہو اور زندہ خدا پر توکل ہو تو پھر تو یہ دو چیزیں مل کر اس کے دل کو ایسا مضبوط بنا دیتی ہیں کہ موت کا ڈر اس کے قریب بھی نہیں آتا.یوروپین قوموں میں اگر ہمیں دلیری نظر آتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ اگرہم مر گئے تو ہماری قوم یتامیٰ و بیوگان کی خبر گیری کرےگی.یہی وجہ ہے کہ مرنے والا موت کی ذرا بھی پروا ہ نہیں کرتا وہ جاتا ہے اور اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے.ایمان اور چیز ہے وہ زیادہ تر انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے نبی پر تازہ بتازہ ایمان لانا نصیب ہو مگر قومی کیریکٹر کی اس ر نگ میں مضبوطی ایمان کے بغیر بھی افرادِ قوم کو بہادر اور نڈر بنا دیا کرتی ہے.وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ.فرمایا اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو یعنی کھانے پینے تجارت اور دوسرے کام کاج میں ان کو اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہی ہیں.تم ایسا کر سکتے ہو.مگر بھائی کہہ کر ذمہ داریاں بھی بتا دیں کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہونا چاہیے جو ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کرتا ہے.بڑا بھائی جس کے سپرد چھوٹے بھائیوں کی نگرانی ہوتی ہے وہ اسی طرح کرتا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے.انہیں کھلاتا پلاتا ہے اور بڑے ہونے پر ان کا مال ان کو دے دیتا ہے اسی طرح یتامیٰ کو بھائی کہہ کر توجہ دلائی کہ چھوٹے بھائیوں سے لینے کی امید نہ رکھو بلکہ انہیں اپنے پاس سے بھی کچھ دینا چاہیے.اور ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جو بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے.وَاللّٰہُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِحِ میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگر تم مصلح بن کر فساد کی بنیاد ڈالو گے اور یتامیٰ
Page 335
کے ساتھ ناروا سلوک کر کے انہیں دکھ پہنچائو گے یا ناواجب پیار کر کے انہیں خراب کرو گے تو دونوں صورتوں میں خدا تعالیٰ کے سامنے تم جواب دہ ہو گے.وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا حکم دے دیتا جس کے نتیجہ میں تمہیں تکلیف ہوتی یعنی وہ کہہ دیتا کہ یتامیٰ کا مال بھی الگ رکھو اور ان کا خرچ بھی برداشت کرو.لیکن اس نے رحم سے کام لیا اور تمہاری سہولت کو اس نے مدنظر رکھا اس سہولت کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ تم یتامیٰ کی تربیت کا خیال نہ رکھویا ان کے اموال کو غصب کرنے کی کوشش کرو.اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.اس میں عزیز اور حکیم کی صفات کا ذکر کر کے پھر دو امور کی طرف توجہ دلائی ایک طرف تو اس امر کی طرف کہ یتیم میں طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حقوق دوسروں سے لے سکے.اس کے متعلق فرمایا کہ اگر وہ عَزِیْز نہیں تو خدا تعالیٰ تو عزیز اور غالب ہے جس طرح تم یتیم پر غالب ہو تمہارے اوپر بھی کوئی غالب ہستی ہے.اگر تم اس کے حقوق کو تلف کرو گے یا ناجائز سختی اوردبائو سے کام لو گے یا اس کا مال کھائو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں پکڑے گا پھر فرمایا تھا کہ یتیم سے نرمی کرو اور اس کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو.اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے تمہیں بھی حکمت سے کام لینا چاہیے اور جس بات میں فائدہ ہو وہی اختیار کرنی چاہیے.ترتیب وربط اوپر کی آیات کے ساتھ ان آیات کا ربط یہ ہے کہ جنگ کے احکام کے سلسلہ میں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس کے نتیجہ میں بہت لوگ شہید ہو جائیں گے اور ان کے بچے یتیم رہ جائیں گے ایسی صورت میں ان سے کیا سلوک کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے زیر تفسیر آیات میں اس سوال کا جواب دے دیا اور اس طرح تمام مضمون ایک لڑی میں پرو دیا.درحقیقت قرآنی مضامین کی ترتیب عام کتب کی ترتیب کے مطابق نہیں بلکہ طبعی ترتیب ہے وہ اپنے مضامین میں جو ترتیب رکھتا ہے وہ اس ترتیب سے علیٰحدہ ہے جو انسان اپنی کتابوں میں رکھتے ہیں.قرآن کریم اس چیز کو جو سب سے پہلے بیان ہونی ضروری ہو بیان کرتا ہے اور پھر اس کے متعلق انسانی قلب میں پیدا ہونےوالے تمام وساوس اور شبہات کا ازالہ کرتا ہے.مثلاً جنگ ہے اس کے متعلق جو سوال پیدا ہوںگے ان کو بیان کرےگا پھر ان سے جو سوال پیدا ہوگا اس کا ذکر کرے گا اور اس میں جن امور کی طرف انسانی ذہن منتقل ہو گا وہ بیان کرتا چلا جائے گا اور چونکہ ایسے سوالات طبعی ہوتے ہیں اس لئے ان کے جوابات کا قلوب پر خاص اثر پڑتا ہے اسی طبعی ترتیب سے اس جگہ بھی کام لیا گیا ہے.چنانچہ جنگ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کا ذکر کر دیا جو جنگ سے براہ راست تعلق رکھنے والی چیزیں تھیں اور جب جُوئے سے اخراجات جنگ پورے
Page 336
کرنےکے طریق سے روک دیا تو طبعی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ اخراجات کس طرح پورے ہوںگے اس کے لئے بتایا کہ ضروریات زندگی پوری کرنےکےبعد جو رقم بچ رہے.وہ خرچ کرنی چاہیے پھر ایک ہی لفظ عفو استعمال کر کے اس میں مختلف مدارج کا ذکر کر کے بتایا کہ ادنیٰ درجہ کونسا ہے اور اعلیٰ درجہ کونسا؟ اس کے بعد یتامیٰ کے حقوق کو لے لیا.کیونکہ جنگ کے بعد لازماً اس سوال نے اہمیت اختیار کرلینی تھی.غرض قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ اس نے اپنے مضامین میں ایک ایسی اعلیٰ درجہ کی ترتیب رکھی ہے جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے ادھر ایک سوال فطرت انسانی میں پیدا ہوتا ہے اور ادھر قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہوتا ہے.وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ١ؕ وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ اور تم مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں نکاح نہ کرو.اور ایک مومن لونڈی خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ١ۚ وَ لَا تُنْكِحُوا ایک مشرک عورت سے خواہ وہ تمہیں (کتنی ہی) پسند ہو یقیناً بہتر ہے.اور مشرکوں سے جب الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا١ؕ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ تک وہ ایمان نہ لے آئیں (مسلمان عورتیں) مت بیاہو.اور ایک مومن غلام ایک مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ١ؕ اُولٰٓىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ١ۖۚ وَ مشرک (آزاد )سے (بھی) خواہ وہ تمہیں (کتنا ہی) پسند ہو یقیناً بہتر ہے.یہ لوگ (تو )آگ کی طرف بلاتے اللّٰهُ يَدْعُوْۤا اِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ١ۚ وَ يُبَيِّنُ ہیں.اور اللہ( تعالیٰ) اپنے حکم کے ذریعہ سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے.اور لوگوں کے لئے اپنی اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَؒ۰۰۲۲۲ ( معرفت کی) علامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں.حل لغات.لَاتنْکِحُوا نَکَحَ یَنْکِحُ سے جمع مخاطب نہی کا صیغہ ہے اور نَکَحَ الْمَرْأَ ۃَ کے معنے ہیں
Page 337
تَزَوَّجَھَا اس نے عورت سے شادی کر لی.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے.مشرک عو ر تو ںسے اُس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوجائیں.یعنی اگر جنگ میں مشرک عورتیں آئیںتو تم اُن سے نکاح نہ کرو.ہاں !اگر وہ ایمان لے آئیںتو پھر بے شک اُن سے نکاح کر سکتے ہو.یہ حکم بھی جنگ کے احکام کے سلسلہ میں ہی دیا گیا ہے کیونکہ ایام جنگ میں مسلمان اپنے گھروںسے بہت دور ہوتے ہیں.اور ہو سکتا ہے کہ اُن میں سے کسی کو مشرکہ عورت سے شادی کرنے کا خیال آجائے.وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ میں مومن لونڈی کو حُرّہ مشرکہ سے اچھا ٹھہرایا ہے.کیونکہ مومنہ کاتوصرف جسم ہی غلامی میں ہوتا ہے مگرحُرّہ مشرکہ کی رُوح شیطان کی غلامی میں ہوتی ہے.اور جسم کی غلامی رُوح کی غلامی کے مُقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی.اِسی طرح حکم دیاکہ مومن عورتیں مشرکوں کے نکاح میں نہ دویہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں.پھر فرماتا ہے کہ ہم نے یہ حکم اس لئے دیا ہے کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں.یعنی جب مشرکہ عورت مسلمان کے گھر میں آئےگی یا مسلمان عورت مشرک سے بیاہی جائےگی تو چونکہ میاں بیوی کے تعلقات کاایک دوسرے پرگہرا اثر ہوتا ہے اس لئے اُن کے یہ تعلقات انہیںدین سے منحرف کرنے والے ثابت ہوںگے.پس مشرک عورتوں یا مردوں سے تعلقات پیدا نہ کرو ورنہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہیںخدائے واحد سے منحرف کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح تمہیںجہنّم کی طرف لے جائیں گے.حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیںجنّت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے.جنّت وہ جگہ ہے جہاںدلوںمیں سے ہرقسم کا کینہ نکل جائے گا.مگرمشرک مرد اورمومن عورت یا مشرک عورت اورمومن مرد کبھی ایک نکتہ پر متحد نہیںہو سکتےکیونکہ توحیداور شرک دونوں میں بُعدالمشرقین ہے.اور جب ان میں مذہبی عقائد اور تمدّن اور تہذیب کے لحاظ سے اتحاد ہی نہیں ہو گا.تو اُن کی اہلی زندگی خوشگوار کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ امریاد رکھنا چاہیے کہ شرعی اصطلاح میں مشرک سے مرادصرف وہ لوگ ہیں جن کی کوئی شریعت نہ ہو.اہِل کتاب اس حکم میں شامل نہیں ہیں.بِاِذْنِهٖ کا لفظ جو اس جگہ بڑھایا گیا ہے ہمیشہ ایسی صورت میں استعمال ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اپنی طرف سے سامان پیدا کرے.خواہ وہ سامان تقدیر عام کے ماتحت ہوں یا تقدیر خاص کے ماتحت.مگر اس کے
Page 338
یہ معنے نہیں کہ قانون قدرت کو توڑ کر خدا تعالیٰ کوئی کام کرتا ہے.بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خاص حکم سے اس کام کو سرانجام دینے کے سامان مہیّا فرماتا ہے.قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے.آخر میں يُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ ہم نے قانونِ نکاح تمہارے سا منے بیا ن کر دیا ہے.اب تمہا راکام یہ ہے کہ تم اِس قانو ن کو مدّنظررکھو اور جنگ میں بھی جبکہ دشمن کی عدا و ت انسا ن کو نا بینا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہد ا یت کے ما تحت چلنے کی کو شش کرو.وَ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ١ؕ قُلْ هُوَ اَذًى ١ۙ فَاعْتَزِلُوا اور یہ لوگ تجھ سے حیض کے( ایام میں عورت کے پاس جانے کے) بارہ میں( بھی) سوال کرتے ہیں.تو کہہ دے کہ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ١ۙ وَ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ١ۚ فَاِذَا وہ ایک ضرر رساں( امر) ہے اس لئے تم عورتوں سے حیض (کے دنوں) میں علیٰحدہ رہو.اور جب تک وہ پاک تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ (وصاف) نہ ہو لیں ان کے پاس نہ جاؤ.پھر جب وہ نہا کرپاک ہو جائیں.تو جد ھر سے اللہ( تعالیٰ) نے تمہیں حکم يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۰۰۲۲۳ دیا ہے.ان کے پاس آؤ.اللہ ان سے جو اس کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں یقیناً محبت کرتا اور( ظاہری و باطنی) صفائی رکھنے والوں سے بھی یقیناً محبت کرتا ہے.حل لغا ت.اَلْمَحِیْضُ اَلْحَیْضُ وَوَقْتُ ا لْحَیْضِ وَمَوْضِعُہٗ.اَلمَحِیْضُ کے معنے(۱) حیض (۲) ایا م حیض اور (۳)حیض کی جگہ کے ہیں.(مفردات) اَذًیاَ لْاَذٰی مَا یَصِلُ اِلَی الْحَیَوَا نِ مِنَ الضَّرَ رِ.اَذٰی کے معنے ہر ایسے ضر ر کے ہیں جو کسی ذی روح کو پہنچے.وَ قَوْلُہٗ یَسْئَلُوْ نَکَ عَنِ الْمَحِیْضِ قُلْ ھُوَاَذًی فَسُمِّیَ ذٰ لِکَ اَ ذًی بِاِعْتِبَا رِ الشَّرْ عِ وَبِاِعْتِبَارِ الطِّبِّ عَلٰی حَسْبِ مَا یَذْکُرُہٗ اَصْحَا بُ ھٰذِہِ الصَّنَاعَۃِ.اور قر آ ن کریم کی آ یت میں اسے اَذًی ایک تو شر عی
Page 339
نقطہ نگا ہ سےکہا گیا ہے.دوسر ے طبّی لحا ظ سے بھی اسے نقصا ن رساںقر ا ر دیا گیا ہے.جیسا کہ تما م اطبّا ء اسے بیا ن کر تے چلے آ ئے ہیں.(مفر دا ت) اِعْتِزَالٌ کے معنے ہیں ا یک طر ف ہو جا نا.تَطَھَّرْنَ تَطَھَّرَتِ الْمَرْاَۃُ کے معنے ہو تے ہیں اِغْتَسَلَتْ عو ر ت نے غسل کیا.(اقر ب) تفسیر.جب مر د و عور ت کا نکا ح کے ذر یعہ تعلق قا ئم ہو جا ئے تو اس کے بعد جو ں جو ں ازدوا جی ذمہ واریا ں سا منے آ تی ہیں انسا نی قلب میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہو تے رہتے ہیں جن کا حل کر نا ضر و ر ی ہو تا ہے.اس جگہ اسی قسم کے ایک سوا ل کا ذکر کر تے ہوئے اس کا جوا ب دیا گیا ہے.فر ما تا ہے لو گ ایام حیض کے با رہ میں تجھ سے سوا ل کر تے ہیں کہ آیاان ایّا م میں مخصوص تعلقا ت قا ئم کئے جا سکتے ہیںیا نہیں؟ فر ما تا ہے تو انہیں کہہ دے کہ حیض تو ا یک نجا ست ہے.پس تمہیں چا ہیے کہ ان ایا م میں جنسی تعلقا ت سے پر ہیز رکھواور اس وقت تک اس پر قا ئم رہو جب تک کہ وہ نہا دھو کر پا ک صا ف نہ ہو جا ئیں.اس جگہ لَا تَقْرَبُوْهُنَّ کے یہ معنے نہیں کہ اِن اَیام میں عور تو ں کو چھو نا یا ہا تھ لگانا یا اُ ن کے پا س بیٹھنا بھی منع ہے.بلکہ اس سے صر ف مخصو ص تعلقا ت کی نفی کی گئی ہے ورنہ حضر ت عا ئشہ رضی اللہ عنہافر ما تی ہیں کہ ر سو ل کر یم صلی اللہ علیہ و سلم ایا م حیض میں بھی اُ ن سے پیا ر کر لیتے اور انہیں اپنے پا س بٹھا لیا کر تے تھے(ترمذی کتاب الطہارۃ باب ما جاء فی مباشرة الحائض).فقہاء میں اس امر کے متعلق اختلا ف پا یا جا تا ہے کہ خو ن حیض بند ہو نے کے بعد مخصو ص تعلقا ت قا ئم کئے جا سکتے ہیں یا نہا نے کے بعد اور اس با رہ میں کچھ تو ایک طر ف چلے گئے ہیں اور کچھ دوسر ی طرف.لیکن اصل با ت یہ ہے کہ حیض بند ہو جانے کے بعد عو رت کے پا س جا ناتو جا ئزہو جاتا ہے.مگر اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ نہا نے دھو نے کے بعد یہ تعلق قا ئم کیا جائے.تطہر کے لئے ر سو ل کر یم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرما یا ہے کہ جب عورت ایّا م حیض سے فا ر غ ہوتو مشک پا نی میں حل کر کے اور اس سے روئی بھگو کر اندرونی ا عضاء کی صفا ئی کر لیا کر ے.(بخاری کتاب الحیض باب غسل المحیض) اور طبّی طو ر پر ثا بت ہے کہ ایسا کیا جائے تو عورت کی صحت اور آئندہ اولاد پر اس کا نہا یت خو شگوا ر اثر پڑتا ہے.فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ اَمَرَکُمُ اللّٰہُ میںحَیْثُ ظر فِ مکا ن ہے اور مر اد یہ ہے کہ تم عورتوں کے پا س اس جگہ سے آؤ جس جگہ کے آنے کا اس نے حکم دیا ہوا ہےاور اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا
Page 340
ہوا ہے.اور وہ یہی ہے جو فَا لْاٰنَ بَا شِرُوْھُنَّ وَابْتَغُوْ ا مَا کَتَبَ اللّٰہُ لَکُمْ (البقرة:۱۸۸)میں بیا ن کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اولا د حاصل کر نے کا جو طبعی طر یق مقرر کر رکھا ہے اس کے مطا بق عمل کر و اور اللہ تعا لیٰ نے جو اولاد تمہا رے لئے مقدر کر ر کھی ہے اس کی جستجو کر و.گو یا عو رتو ں سے تم ایسا ہی تعلق رکھو جس کے نتیجہ میں اولا د پیدا ہو.کوئی غیر فطر ی طر یق اختیا ر نہ کرو.يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس امرکی طر ف تو جہ دلا ئی ہے کہ اگر تم سے کبھی کوئی گنا ہ سر زد ہو جا ئے تو اس کے فو راً بعد تمہا ر ے دل میں اس گنا ہ پر ندامت پیدا ہو نی چا ہیے اور تمہیں اس سے تو بہ کر نی چا ہیے کیونکہ اللہ تعا لیٰ توبہ کر نیوالو ں سے محبت کر تا ہے.دو سرے توّ اب اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بار بار خدا تعالیٰ کی درگاہ میں جاتا اور اس سے دُعا ئیںکر تا رہے.اِس لحا ظ سے يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ کے یہ معنے ہیں کہ وہ لو گ جو یقین رکھتے ہیں کہ ہما ر ے تما م کا م دعاؤںسے و ا بستہ ہیں اور قدم قدم پر وہ خدا تعا لیٰ کی طر ف رجو ع کر تے اور اس سے مدد طلب کر تے ہیں وہ با لآخر اللہ تعا لٰے کی محبت حا صل کر نے میں کا میا ب ہو جا تے ہیں.گو یا گناہو ں پر ندا مت اور توبہ کا اظہا ر اور ہر مشکل گھڑی میں اللہ تعا لیٰ کی طر ف ر جو ع یہ دو ذرائع ایسے ہیں جن سے خدا تعالیٰ کی محبت کا دروازہ انسان کے لئے کھل جا تا ہے.اسی طر حيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ میں بھی دوامور کی طر ف تو جہ دلا ئی گئی ہے ایک تو اس امر کی طرف کہ اللہ تعا لیٰ صفا ئی رکھنے وا لو ں سے محبت کر تا ہے.درحقیقت نظا فت پسندی انسا نی تقاضو ں میں سے ایک اہم تقاضا ہے جسم کو صا ف رکھنا.منہ کو صا ف رکھنا.کپڑوں کو صا ف ر کھنا.اور ایسی اشیاء کااستعما ل کر نا جو نا ک کی قو ت کو صد مہ پہنچا نے والی نہ ہو ں بلکہ اس کے لئے مو جب را حت ہوں.اس تقا ضا کو لوگو ں نے غلطی سے نیکی اور تقویٰ کی اعلیٰ را ہو ں پر چلنے وا لوں کے طر یق کے خلاف سمجھ لیا تھا اور ایک ایسی راہ اختیا ر کر لی تھی جس کے نتیجہ میں یا تو خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ طیّب اشیاء بیکار ہو کر رہ جائیں یا خدا تعالیٰ کے بندے ان طیّب اشیاء کو استعمال کر کے گنہگا ر قرا ر پا ئیں.رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم نے اس بنا وٹی نیکی اور جھو ٹے تقو یٰ کی چا در کو بھی چا ک کر دیا اور حکم دیا کہ اللہ تعا لیٰ خو د پا ک ہے اور پا ک رہنے والو ں کو پسند کر تا ہے.چنا نچہ آ پ اکثر غسل فر ما تے.پھرکئی امو ر کے سا تھ غسل آ پ نے وا جب قرار دے دیا(ابو داؤد کتاب الطہارۃ باب فی الغسل للجمعة) چو نکہ انسا ن اپنے گھر کے اشغا ل کی وجہ سے صفا ئی میں سُستی کر بیٹھتا ہے اس لئے آ پؐ نے خدا تعا لیٰ کے حکم سے میاں بیوی کے تعلقات کے سا تھ غسل کو وا جب قر اردے دیا(ترمذی کتاب الطہارۃ باب ما جاء اذا التقی الختانان وجب الغسل).اِسی طر ح پا نچو ں نما زوں سے پہلے آ پ ان اعضا ء کو دھو تے جو عا م طو ر پر گر دو غبار کامحل بنتے رہتے ہیںاور دوسروں کو بھی اس امر پر
Page 341
عمل پیرا ہو نے کا حکم دیتے (ترمذی کتاب الطہارۃ باب الوضو ء لکل صلوٰة).کپڑوں کی صفا ئی کو آ پ پسند فرماتے.جمعہ کے دن دُھلے ہوئے کپڑے پہن کر آ نے کا حکم دیتے اور خو شبو کو خو د بھی پسندفرماتے اور اجتماع کے مو ا قع کے لئے بھی خو شبو لگا نا پسند فر ما تے.جہا ںاجتما ع ہو نا ہو چو نکہ وہا ں مختلف قسم کے لو گ جمع ہو تے ہیں اور متعدی بیما ریو ں کے پھیلنے کا خطرہ ہو تا ہے اس لئے آ پ وہا ں خو شبودار مصا لحہ جا ت جلا نے اور ان جگہو ں کو صا ف رکھنے کا حکم دیتے(مشکٰوۃ کتاب الصلوٰۃ باب التنظیف و التکبیر ).بد بو دار اشیاء سے پر ہیز فر ما تےاور دوسر وں کو بھی اس سے رو کتے کہ بد بودار اشیاء کھا کر ا جتما ع کی جگہوں میں آئیں(ترمذی ابواب الاطعمة باب ما جاء فی کراہیة اکل الثوم و البصل).غر ض جسم کی صفا ئی.لبا س کی پا کیزگی.اور نا ک کے احسا س کا آ پ پو را خیال رکھتے.اور دوسر و ں کو بھی ایسا ہی کر نے کا حکم دیتے.ہا ں یہ ضر ور فر ما تے کہ جسم کی صفا ئی میں اس قدر منہمک نہ ہو جاؤ کہ رُوح کی صفا ئی کا خیا ل ہی نہ رہے.اور لبا س کی پا کیزگی کا اس قدر خیا ل نہ رکھو کہ ملک و ملّت کی خدمت سے محروم ہو جاؤ اور غر یب لوگوں کی صحبت سے احتر ا ز کر نے لگو.اور کھا نے میں اس قدر احتیا ط نہ کر و کہ ضر و ری غذا ئیں تر ک ہو جا ئیں.ہا ں یہ خیال رکھوکہ اہلِ مجلس کو تکلیف نہ ہو تا کہ اچھے شہر ی بنو.اور لو گ تمہا ری صحبت کو نا گو ا ر نہ سمجھیں بلکہ اسے پسند کریں اور اس کی جستجو کر یں.غر ض لوگو ں نے تو کہا کہ صفا ئی اور خو شبو سے بچو کہ وہ جسم کو پا ک مگر دل کو نا پا ک کر تی ہےلیکن اسلا م نے کہا يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.خدا تعا لیٰ ظا ہر ی اور با طنی صفائی رکھنے وا لو ں کو پسند کر تا ہے گو یا اسلا م نے اپنے اس اعلا ن سے عیسا ئیو ں اور ہندوؤں کے ان تما م فر قوں کا رد کر دیا جن میں بزرگا نِ دین کے لئے پا ک و صا ف رہنا اور خو شبو کا استعما ل با لکل حرام سمجھا جا تا تھا اور جن میں گندے اور بد بودار لبا س کا استعمال اور ناخن نہ کٹوانااور جسم کی میلنہ اتارنا بزرگی کی ایک بہت بڑی علا مت سمجھی جا تی تھی.اسلام نے اس نظر یہ کو با طل قر ار دیتے ہو ئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگو ںسے محبت رکھتا ہے جواللہ تعالیٰ کی طر ف بار با ر رجو ع کر نے والے بھی ہو ں اور اُ ن کا جسم اور لبا س بھی صا ف ستھر ا ہو اور وہ ہر قسم کی غلا ظت سے دور ہنے وا لے ہوں.ان معنو ں کے لحا ظ سے يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ کہہ کر اس طرف تو جہ دلا ئی کہ خدا تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ جب عورتیں غسل کر لیں تب اُن کے سا تھ صحبت کی جا ئے اس سے پہلے ان کے پا س جا نا يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ کے خلا ف ہے.مُتَطَھِّرٌ کے دو سرے معنے تکلّف کےسا تھ پا کیزگی اختیا ر کرنےوا لے کے ہیں.اس لحا ظ سے يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ میں اس طر ف اشا رہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ان لو گو ں سے محبت کر تا ہے جو اس کے ہم جنس بننے کی کو شش کر تے ہیں.پس خدا تعالیٰ کی جو صفات قر آن کر یم میں بیا ن ہو ئی ہیں تم اُ ن کی نقل کر نے کی کو شش کر و.تم حَي
Page 342
نہیں بن سکتے لیکن تم بیما ر کا علاج کر کے حیّ کی نقل تو کر سکتے ہو.تم مُمِیْت نہیں بن سکتے لیکن تم بدی کا خا تمہ کر کے ممیت کی نقل تو کر سکتے ہو تم خا لق نہیں بن سکتے لیکن تم اچھی اولا د پیدا کر کے خالق کی نقل تو کر سکتے ہو.پس فرمایا اگر تم میری محبت حا صل کر نا چا ہتے ہو تو تم میر ی نقل کر نا شر و ع کر دو اور میر ی صفا ت کو اپنے اند ر پیدا کر و اس کے نتیجہ میں تم سے محبت کر نے لگ جا ؤںگا.نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ١۪ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ١ٞ وَ تمہاری بیویاں تمہارے لئے( ایک قسم کی )کھیتی ہیں.اس لئے تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی کے پاس آؤ.قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ١ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ١ؕ وَ اور اپنے لئے (کچھ )آگے بھیجو.اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ تم اس کے روبرو ہونے والے ہو.بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ۰۰۲۲۴ اور تو مومنوں کو( اس دن کے بارے میں) خوشخبری دے.حلّ لُغا ت.اَنّٰی کے معنے اَ یْنَ، مِنْ اَ یْنَ اور کَیْفَ کے ہیں.یعنی ’’جہا ں‘‘.’’جہا ںسے‘‘.’’جب‘‘ اور ’’ جس طرح‘‘ (اقر ب) تفسیر.اِس آ یت میں عو رت کو کھیتی قر ا ر دے کراللہ تعالیٰ نے بنی نو ع انسان کو اس امر کی طر ف تو جہ دلا ئی ہے کہ(۱) تم اپنی کھیتی کو پھل دار بنا نے کی کو شش کرو.اِسی کی طر ف رسو ل کر یم صلی اللہ علیہ و سلم کی یہ حد یث بھی اشا رہ فر ما تی ہے کہ تَزَوَّجُواالْوَلُوْدَ الْوُدُوْدَ فَاِنِّیْ مُکَا ثِرٌ بِکُمُ الْاُمَمَ(ابو داؤد کتاب النکاح باب النّھی عن تزویج من لم یلد من النساءو نسائی کتا ب النکاح باب کراھیة التزویج العقیم) یعنی تم ایسی عورتوں کے سا تھ شا دی کیا کر و جو زیادہ اولا د پیدا کر نے وا لی اور اپنے خا وندوں کے ساتھ محبت کر نے والی ہو ں.کیو نکہ میں دوسر ے نبیو ں کی اُمتو ں کے مقا بل پر اپنی امّت کی کثر ت پر قیا مت کے دن فخر کر وںگا.(۲)عو رتو ں سے ایسا سلو ک کر و کہ نہ اُ ن کی طا قت ضائع ہو.اور نہ تمہا ری.اگر کھیتی میں بیج زیا دہ ڈال دیا جائے توبیج خر اب ہو جا تا ہے.اور اگر کھیتی سے پے در پے کا م لیا جا ئے تو کھیتی خر ا ب ہو جا تی ہے.پس ہرکا م ایک حد
Page 343
کے اندر کر و.جس طر ح عقلمند انسا ن سو چ سمجھ کر کھیتی سے کا م لیتا ہے.اس آیت سے یہ بھی نکل آیا کہ بعض حا لا ت میں بر تھ کنٹرول بھی جا ئز ہے.چنا نچہ کھیتی میں سے اگر ایک فصل کاٹ کر معاً دوسری بو دی جا ئے تو دوسر ی فصل اچھی نہیں ہو تی.اور تیسری اس سے بھی زیا دہ خراب ہو تی ہے.اسلا م نے اولا د پیدا کر نے سے روکا نہیں بلکہ خو د فر ما یا ہے کہ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ تم اپنی عو رتو ں کے پا س اِس لئے جا ؤ کہ آ گے نسل چلے اور تمہا ری یا دگار قا ئم رہے لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ کھیتی کے متعلق خداتعا لیٰ کے جس قا نو ن کی تم پابندی کر تے ہو اسی کو اولاد پیدا کر نے میں بھی مّد نظر رکھو.اگر عو ر ت کی صحت مخدو ش ہو یا بچہ کی پر ورش اچھی طر ح نہ ہوتی ہو تو اس وقت اولاد پیدا کر نے کے فعل کو روک دو.(۳)یہ بھی بتایا کہ عو رت سے ایسا تعلق رکھو جس کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہو.اس سے خلافِ وضع فطرت فعل کی مما نعت نکل آ ئی.چو نکہ قر آ ن کر یم خدا تعالیٰ کا کلا م ہے اس لئے وہ با ت کو اُسی حد تک ننگا کر تا ہے جس حد تک اخلا ق کو کوئی نقصا ن نہ پہنچتا ہو.لو گ اَنّٰى شِئْتُمْ سے غلط استدلا ل کر تے ہیں.حا لا نکہ یہ الفا ظ کہہ کر تو خدا تعالیٰ نے ڈرا یا ہے کہ یہ تمہا ری کھیتی ہے اب جس طر ح چاہوسلو ک کر و.لیکن یہ نصیحت یادرکھو کہ اپنے لئے بھلائی کا سا ما ن ہی پیدا کر نا.ورنہ اس کا خمیا زہ بھگتو گے.لوگ جب اپنی لڑ کیو ں کی شا دی کر تے ہیں تو لڑ کے وا لو ں سے عمو ماً کہا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی تمہیں دےدی ہے.اب جیسا چا ہو اِس سے سلوک کرو.اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ تم بے شک اِسے جوتیاں مارا کرو.بلکہ مطلب یہ ہوتاہے کہ یہ تمہاری چیز ہے اسےسنبھا ل کر رکھنا.پس اَنّٰى شِئْتُمْ کا مطلب یہ ہے کہ عورت تمہاری چیز ہے اگر خراب سلوک کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے لئے بھی برا ہوگا اور اگر اچھا سلوک کرو گے تو اچھا ہو گا.مگر لوگوں نے بیو قوفی سے اَنّٰى شِئْتُمْ کا یہ مطلبلے لیا کہ’’اَنھے واہ‘‘ یعنی اندھا دھند کرو.آ ریوں نے خصو صیت سے اس آ یت پر اعتر ا ض کیا ہے کہ اسلا م نے مر دوعو رت کے تعلقات کے بارہ میں اپنے متبعین کو غیر فطری طر یق اختیا ر کر نے کی اجا زت دی ہے (ستیارتھ پرکاش مترجم باب ۱۴ اعتراض ۳۸ زیر آیت ھٰذا) حالانکہ ان کا یہ خیا ل با لکل غلط ہے.اَنّٰى شِئْتُمْ کے یہ معنے نہیں کہ اب خلا ف وضع فطر ی فعل بھی تمہارے لئے جا ئز ہو گیا ہے.بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ جب تمہا ری بیویاں تمہارے لئے کھیتی کی حیثیت رکھتی ہیں تو اب تمہا را اختیا ر ہے کہ تم جس طر ح چاہو اُن سے سلو ک کر و.یعنی چا ہو تو اپنی کھیتی کو تباہ کر لو اور چا ہو تو اس سے ایسے فو ائد حا صل کرو جن سے دنیا میں بھی تم نیک نامی حا صل کر و اور آ خر ت میں بھی اپنی روح کو خوش کر سکو.دنیا میں کو ئی احمق زمیندار ہی ہوگا جو نا قص بیج استعما ل کر ے یا بیج ڈا لنے کے بعد کھیتی کی نگرا نی نہ کر ے.اوراچھی فصل حا صل کر نے کی کو شش نہ کر ے مگر عو رتو ں کے معا ملہ میں با لعمو م اس اصو ل کو نظر اندا ز کر دیا جا تا ہے اور
Page 344
نہ تو جسما نی اور اخلا قی لحا ظ سے بیج کی صحیح طور پر حفا ظت کی جا تی ہے نہ عو رت کی صحت اور اُ س کی ضر و ر یا ت کا خیال رکھا جا تا ہے اور نہ بچو ں کی صحیح رنگ میں تربیت کی جا تی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ مر دوں کی صحت کو بھی نقصا ن پہنچتا ہے اور عو رت کی صحت بھی بر با د ہو جا تی ہے اور بچے بھی قو م کا مفید وجو د ثا بت نہیں ہو تے.اللہ تعا لٰے نے اس آیت میں بنی نو ع انسان کو اِسی اہم نکتہ کی طر ف تو جہ دلا ئی ہے اور فر ما یا ہے کہ جس طر ح تم اپنی کھیتی کی حفا ظت کرتے ہواور اعلیٰ درجہ کی فصل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہواسی طرح تمہارا فرض ہے کہ تم عورت کی بھی حفاظت کرو اورآ ئندہ نسل کی تعلیم و تر بیت کی طر ف خاص طو ر پر تو جہ دو تا کہ تمہا ری کھیتی سے ایسا روحا نی غلہ پیدا ہو جو دنیا کے کا م آئے اور انہیں ایک نئی زندگی بخشے.وَ قَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ میں بتا یا کہ تم وہ کا م کر و جس کا آ ئندہ نتیجہ تمہا رے لئے اچھا نکلے.یعنی طبّی لحا ظ سے بھی اور نسلی لحا ظ سے بھی.یہ حصّہ وَابْتَغُوْامَاکَتَبَ اللّٰہُ لَکُمْ کے مشا بہ ہے اور مرا د یہ ہے کہ آ ج کے بچے کل کے با پ بننے وا لے ہیں.اس لئے تم ایسی اولا د پیدا کرو جو تمہا رے نا م کو روشن کرنے والی ہو اور آخر ت میں بھی تمہا ری عزت اور نیک نا می کا موجب ہو.اسی طر ح اس کے ایک معنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا بھی ایک کھیتی ہے جس سے آ خر ت میں کا م آ نے وا لا غلہ پیدا ہو تا ہے.اس لئے تمہیں چا ہیے کہ اِس کھیتی کی طر ف بھی اپنی نگا ہ رکھو اور ایسے اعما ل بجا لا ؤ کہ جس طرح ایک دا نہ سے سا ت با لیں اور ہر با ل میں سو سو دانہ پیدا ہو تا ہے.اسی طر ح تمہا را ایک ایک عمل خدا تعالیٰ کے ہزاروں ہزار انعا ما ت کو تمہا ری طر ف کھینچ لا نے والا ہو.وَ لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ۠ اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا اور تم نیک سلوک کرنے تقویٰ کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے (کے معاملات) میں اللہ کو اپنی قسموں کا وَ تُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ١ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۰۰۲۲۴ نشانہ نہ بناؤ.اور اللہ خوب سننے والا (اور )بہت جاننے والا ہے.حل لغا ت.عُرْضَۃً مَا یُجْعَلُ مَعْـرَضًالِلشَّیْءِ.عرضہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے کسی دوسری چیز کا نشا نہ بنا لیا جا ئے.اسی طر ح عُر ضہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جسے ضرورت کے پو را کر نے کا ایک ذریعہ بنا لیا جا ئے.کہتے
Page 345
ہیں اَلْبَعِیْرُعُرْضَۃٌلِلسَّفَرِ سفر پیش آئے تو اونٹ عُرضہ بن جاتا ہے.مُراد یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ سفر کی تکلیف کو دُور کیا جاتا ہے (مفردات) اِسی طرح عُرْضَۃٌ حِیْلَۃٌ فِی الْمُصَارَعَۃِ کُشتی کے داؤ پیچ کو بھی کہتے ہیں.(اقرب) اَیْمَانٌ جمع ہے اس کا مفرد یَمِیْنٌ ہے اور یَمِیْنٌ کے معنے ہیں.(۱)دائیں جہت یا دایاں حصّہ جسم (۲) قسم (۳) برکت (۴) قوت (اقرب) اور محاورہ میں اس شے کو بھی کہتے ہیں جس کے بارہ میں قسم کھائی جائے.رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت عبد الرحمٰن بن سمرۃؓسے فرمایا اِذَا حَلَفْتَ عَلٰی یَمِیْنٍ فَرَأَ یْتَ غَیْرَھَاخَیْرً ا مِّنْھَا فَاْتِ الَّذِیْ ھُوَ خَیْرٌوَکَفِّرْ عَنْ یَمِیْنِکَ یعنی جب تو کسی چیز کے بارہ میں قسم کھائے (اس کے لئے آپؐنے لفظ یَـمِیْن استعمال فرمایا)اور اس کے بعد اُس سے اچھا کام تجھے سُوجھ جائے تو تُو وہ کام جو بہتر ہے اختیار کر اور اپنی قسم کاکفارہ دے دے.(الکشاف) تفسیر.فرماتا ہے.اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ.یعنی جس طرح ایک شخص نشانہ پر بار بار تیر مارتا ہے اسی طرح تم بار بار خدا تعالیٰ کی قسمیں نہ کھا یا کرو.کہ ہم یوں کر دیںگے اور ووں کر دیںگے.اَنْ تَبَرُّوْاوَتَتَّقُوْاوَتُصْلِحُوْابَیْنَ النَّاسِ یہ ایک نیا اور الگ فقرہ ہے.جو مبتداء ہے خبرمحذوف کا.اور خبر مخدوف اَمْثَلُ وَاَوْلٰی ہے.یعنی بِرُّکُمْ وَ تَقْوَاکُمْ وَاِصْلَاحُکُمْ بَیْنَ النَّاسِ اَمْثَلُ وَاَوْلٰی اِ س کے معنے یہ ہیں کہ تمہا را نیکی اور تقویٰ اختیا رکر نا اور اصلا ح بین النا س کرنا زیا دہ اچھا ہے.صر ف قسمیں کھا تے رہنا کہ ہم ایسا کر دیںگے کو ئی درست طر یق نہیں.تمہیں چاہیے کہ قسمیں کھا نے کی بجا ئے کا م کر کے دکھا ؤ.پہلے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ زجاؔ ج جو مشہور نحو ی اور ادیب گذرے ہیں انہو ں نے یہی معنے کئے ہیں.(بحر محیط زیر آیت ھٰذا).دو سر ے معنے اس کے یہ ہیں کہ اللہ تعا لیٰ کو روک نہ بنا ؤ اُن چیزوں کے لئے جن پر تم قسم کھا تے ہو.یعنی بِرّ کر نا تقویٰ کر نا اور اصلا ح بین الناس کر نا.اِس صو رت میں یہ تینو ں اَیْمَان کا عطفِ بیا ن ہیں اور اَیْمَان کے معنے قسمو ں کے نہیں بلکہ اُ ن چیزو ں کے ہیں جن پر قسم کھائی جا تی ہے.مطلب یہ کہ اپنا پیچھا چھڑا نے کے لئے نیک کا م کی قسم نہ کھا لیا کرو.تا کہ یہ کہہ سکو کہ کیا کروں چو نکہ میں قسم کھا چکا ہو ں.اس لئے نہیں کر سکتا.مثلاً کسی ضر ورت مند نے روپیہ ما نگا تو کہہ دیا کہ میںنے تو قسم کھا لی ہے کہ آئندہ میں کسی کو قر ض نہیں دوں گا.علّامہ ابو حیّا ن کہتے ہیں کہ اس فقرہ کو ایْمَان کا عطفِ بیا ن بنا نے کی بجا ئے بدل بنا نا اچھا ہے.کیو نکہ عطفِ بیان اکثر اَعْلَامْ (یعنی کسی چیز کا معیّن نام) ہوتے ہیں(بحر محیط زیر آیت ھٰذا).بہرحال دونوں صورتوںمیں اس کے معنے یہ ہیں کہ اگر کوئی نیکی اور تقویٰ اور اصلاح بین الناس کے کام کےلئے تمہیںکہے تو تم یہ نہ کہوکہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے مَیں
Page 346
یہ کام نہیں کر سکتا.تیسرے معنے یہ ہیں کہ اس ڈر سے کہ تمہیں نیکی کرنی پڑے گی خدا تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ.اس صورت میں اَنْ تَبَرُّوْا مفعول لِاَجْلہٖ ہے اور اس سے پہلے کَرَاھَۃً مقدّر ہے.اور مُراد یہ ہے کہ اگر اچھی باتیں نہ کرنے کی قسمیں کھاؤگے تو ان خوبیوں سے محروم ہو جاؤگے اس لئے نیکی ،تقویٰ اور اصلاح بین الناس کی خاطر اس لغو طریق سے بچتے رہو.درحقیقت یہ سب معنے آپس میں ملتے جلتے ہیں.صرف عربی عبارت کی مشکل کو مختلف طریق سے حل کیا گیا ہے.جس بات پر سب مفسّرین متفق ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نہ کرو کہ خداتعالٰے کو اپنی قسموں کا نشانہ بنالو.یعنی اُٹھے اور قسم کھا لی.یہ ادب کے خلاف ہے اور جو شخص اس عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بسا اوقات نیک کاموں کے بارہ میں بھی قسمیں کھا لیتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروںگا اور اس طرح یا تو بے ادبی کا اور یانیکی سے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے یا یہ کہ بعض اچھے کاموں کے متعلق قسمیں کھا کر خدا تعالیٰ کو ان کے لئے روک نہ بنا لو.اِن معنوں کی صورت میں داؤ پیچ والے معنے خوب چسپا ں ہوتے ہیں.اور مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ صدقہ و خیرات سے بچنے کے لئے چالیں چلتے ہیں اور داؤ کھیلتے ہیں اور بعض خدا تعالٰے کی قسم کو جان بچانے کا ذریعہ بتا تے ہیں.گویا دوسرے سے بچنے اور اُسے پچھاڑنے میں جو داؤ استعمال کئے جاتے ہیں اُن میں سے ایک خدا تعالیٰ کی قسم بھی ہوتی ہے.پس فرماتا ہے.اللہ تعالیٰ کے نام کو ایسے ذلیل حیلوں کے طورپر استعمال نہ کیا کرو.میرے نزدیک سب سے اچھی تشریح علاّمہ ابو حیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنے احسان اور نیکی وغیرہ کے آگے روک بنا کر کھڑا نہ کر دیا کرو.وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ میں بتایا کہ اگر تمہیں نیکی اور تقویٰ اور اصلاح بین الناس کے کام میں مشکلات پیش آئیں تو خدا تعالیٰ سے ان کا دفعیہ چاہو اور ہمیشہ دُعاؤں سے کام لیتے رہو کیونکہ یہ کام دُعاؤں کے بغیر سرانجام نہیں پا سکتے.اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے.اگر تم اُس کی طرف جھکو گے تو وہ اپنے علم میں سے تمہیں علم عطا فرمائے گا اور نیکی اور تقویٰ کے بارہ میں تمہارا قدم صرف پہلی سیڑھی پر نہیں رہے گا بلکہ علمِ لدنّی سے بھی تمہیں حصّہ دیا جائے گا.
Page 347
لَا يُؤَاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ اللہ (تعالیٰ )تمہاری قسموں میں (سے) لغو (قسموں) پر تم سے مؤاخذہ نہیں کرے گا.ہاں جو( گناہ) يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ۰۰۲۲۶ تمہارے دلوں نے (بالارادہ) کمایا اس پر تم سے مؤاخذہ کرے گا.اور اللہ بہت بخشنے والا (اور) بردبار ہے.حل لغات.حَلِیْمٌ حِلْمٌ سے ہے اور اس کے معنے صبر کر نے والے کے بھی ہوتے ہیں اور اِ سی طرح اِ س کے معنے بُر دبا ر کے بھی ہیں.یعنی جس میں طیش نہ ہو.یونہی جو ش میں آ کر اندھا دھند کا م نہ کر تا ہو.حِلْمٌ جہالت اور بیوقو فی کے مخا لف معنے بھی دیتا ہے.اور علم اور سمجھ کے بھی نیز اس کے معنے عقل کے بھی ہیں.(اقرب) تفسیر.فر ما تا ہے.اللہ تعالیٰ لغو قسمو ں پر تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں کر ے گا.اس جگہ لغو قسموں سے تین قسم کی قسمیںمرا د ہیں.اوّل عا دت کے طو ر پر قسمیں کھا نا.یعنی ہر وقت وَاللّٰہِ.بِاللّٰہِ.ثُمَّ تَا للّٰہِ کہتے رہنا.دوم ایسی قسم جس کا کھا نے والا یقین رکھتا ہو کہ وہ درست ہے لیکن اس کا یقین غلط ہو.مثلاً کسی شخص کے متعلق قسم کھا نا کہ وہ وہا ں ہے حا لا نکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آ نے کے بعد وہا ں سے چلا گیا ہو.سو م ایسی قسم جو شد ید غصہ کے وقت کھا ئی جا ئے.جب ہو ش و حوا س ٹھکا نے نہ ہو ں یا حرا م شے کے استعما ل یا فر ض و وا جب عمل کے تر ک کے متعلق کسی وقتی جو ش کے ما تحت قسمیںکھا لینا.یہ سب قسمیں لغو ہیں اور ان کے تو ڑنے پر کو ئی کفا رہ نہیں.چو نکہ پہلی آ یت میںاللہ تعالیٰ نے قسمو ں سے روکا تھا اس لئے اب بتا یا کہ مؤ ا خذہ صر ف ایسی قسموں پر ہو گا جن کو لغو قرار نہ دیا جا سکےمگر اس کے یہ معنے نہیں کہ چو نکہ مؤ اخذہ نہیں ہو گا اِس لئے اب کسی احتیا ط کی بھی ضر ورت نہیںبیشک رات دن لغو قسمیں کھا تے رہو.کیو نکہ اللہ تعالیٰ نے مو منو ں کے متعلق یہ بھی بیا ن فر ما یا ہے کہ وَالَّذِیْنَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ (المؤمنون :۴) مو منوں لغو با توں سے بھی پر ہیز کر تے ہیں.پس لغو قسمیں کھا نے والا یقیناً مخطی یا گنہگا رہے اور اُسے اپنے گنا ہ پر تو بہ اور ندامت کا اظہا ر کر نا چا ہیے.ہا ںاُن کے تو ڑنے پر کسی کفارہ کی ضر و رت نہیں.اِ سی مفہو م کو ادا کر نے کے لئے اللہ تعالیٰ نے لَا يُؤَاخِذُكُمُ کے الفا ظ بیا ن فر مائے ہیں.یعنی اگر وقتی جو ش کے ما تحت ایسی قسم کھا لی جا ئے تو گنا ہ نہ ہوگا ہا ں اگر جا ن بو جھ کر کو ئی شخص ایسی قسم کھا ئے تو اُسے یقیناً گنا ہ ہو گا.بعض لوگو ںنے لَایُؤَاخِذُ کے معنے لَا بَاْسَ بِہٖ یالَاحَرَجَ فِیْ ذٰلِکَ کے کئے ہیں کہ ا س میں کوئی حرج نہیں.
Page 348
مگر یہ صحیح نہیں.یہا ں پر ایک تو مؤاخذہ کی نفی کی ہے اور دوسر ے لغو قسموں سے پر ہیز کی تا کید کی ہے.وَلٰکِنْ یُؤَاخِذُکُمْ بِمَاکَسَبَتْ قُلُوْبُکُمْ میں گذشۃ تینو ں قسموں کی نفی کر دی گئی ہے کیو نکہ قسم عا دتاً ہو یا غصّہ اور بے احتیا طی سے ہو ان میں سے کو ئی قسم بھی عمداً نہیں ہو تی بلکہ بعض وقت تو انسا ن کو پتہ بھی نہیں لگتا اور وہ قسم کھا جا تا ہے.پس کسب قلب سے مرا د یہی ہے کہ عمداً قسم کھا ئی جا ئے.ایک و ا قعہ کے متعلق وہ سمجھتا ہوکہ یو ں ہے مگر پھر اس کے خلا ف قسم کھا جا ئے.ایسی قسم کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے سو رہ ما ئدہ میں اِ ن الفا ظ میں بیا ن فر ما یا ہے کہ فَكَفَّارَتُهٗۤ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ١ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ١ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ(الما ئد ۃ: ۹۰) یعنی قسم تو ڑنے کا کفا رہ دس مسا کین کو متوسط درجہ کا کھا نا کھلا نا ہے.ایسا کھا نا جو تم اپنے گھر وا لو ں کو کھلا تے ہو.یا اُ ن کے لئے لبا س مہیا کر نا ہے.یا ایک غلا م کو آ زاد کر نا ہے.لیکن جسے اس با ت کی تو فیق نہ ہو اُس پر تین دن کے روزے وا جب ہیں.یہ تمہا ری قسمو ں کا کفا رہ ہے جبکہ تم قسم کھانے کےبعد انہیں تو ڑ دو.یہا ں ایک سوا ل پیدا ہو تا ہے کہ آ یا قر آن کر یم کی قسم کھا نا جا ئز ہے یا نہیں؟ اس کا جوا ب یہ ہے کہ اگر ملکی رواج کو مدّ نظر رکھ کر قر آ ن کر یم کی قسم کھا ئی جائے تو میر ے نزدیک جا ئز ہے.کیو نکہ مدّ مقا بل پر قر آ ن کر یم کی قسم کھا نے سے غیر معمو لی اثر پڑ تا ہے.يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ سے یہ بھی معلو م ہو تا ہے کہ جس شخص کے دل میں بد اخلاقی کے خیا لا ت آ تے ہیں.مثلاً اپنے بھائی کی نسبت بد ظنّی کا خیال پیدا ہو تا ہے.یا تکبّر یا حسد یا نفرت کا جذبہ پیدا ہو تا ہے لیکن وہ اس خیال کو دبا لیتا ہے تو اس کا یہ خیا ل یا جذبہ بد اخلا قی نہیں سمجھا جا ئےگا کیو نکہ ایسا شخص درحقیقت بد اخلا قی کا مقا بلہ کر تا ہے اور تعر یف کا مستحق ہے، اسی طر ح جس شخص کے دل میں ایک آ نی خیا ل نیکی کا آ ئے یا آ نی طو ر پر حسن سلو ک کی طر ف اس کی طبیعت ما ئل ہو لیکن وہ اس کو بڑھنے نہ دے تو ایسا شخص بھی صا حب اخلا ق نہیں سمجھا جائےگا گو اُس کے اِ س وقتی جذبہ کو بھی قا بلِ تعر یف قر ار دیا جا ئےگا کیو نکہ اخلا ق وہ ہیں جو انسا ن کے ارادہ کا نتیجہ ہوں لیکن مذکو رہ با لا دونوں صورتوں میں اچھے یا بُر ے خیا لا ت ارادہ کا نتیجہ نہیں ہو تے بلکہ بیرونی اثر ات کے نتیجہ میں بلا ارادہ پیدا ہو جا تے اور اُسی وقت زا ئل ہو جاتے ہیں.اس نکتہ کو قر آ ن کر یم نے اِن الفا ظ میں بیا ن فر ما یا ہے کہ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ.اللہ تعالیٰ تم کو صرف ان خیالات پر پکڑے گا جو ارادہ اور فکر کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں نہ ان پر جو اچانک پیدا ہو جاتے ہیں اور تم ان کو فوراً اپنے دل سے نکال دیتے ہو.رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم اس کی تشریح یوں
Page 349
فرماتے ہیں کہ اچانک بد خیال پیدا ہونے پر جو شخص اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ایسا شخص نیکی کا کام کرتا ہے.اور اجر کا مستحق ہے آپ فرما تے ہیں وَ مَنْ ھَمَّ بِسَیِّئَۃٍ فَلَمْ یَعْمَلْھَاکَتَبَھَا اللّٰہُ عِنْدَہٗ حَسَنَۃً کَامِلَۃً (بخاری کتاب الرقاق باب من ھمّ بحسنۃ و بسیّئۃ)اگر کسی شخص کے دل میں بُرا خیال پیدا ہو اور وہ اس کو دبا لے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ایک پوری نیکی لکھے گا.یعنی بدخیال کے دبانے کی وجہ سے اس کو نیک بدلہ ملے گا.وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ میں غفور کے لفظ سے بتا دیا کہ اگر تم ایسی قسموں سے اجتناب کروگے اور توبہ کروگے توہم تمہیںبخش دیں گے.اور حلیم کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ ہم نے لغو قسموں پر اس لئے گرفت نہیں کی کہ اگر ہم ان قسموں پر گرفت کرنا شروع کر دیں تو تمہارا بچنا مشکل ہو جائے.لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ١ۚ جو لوگ اپنی بیویوںکے متعلق قسم کھا( کر ان سے علیٰحدگی اختیار کر) لیتے ہیں.ان کے لئے (صرف) چار مہینےتک فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۰۰۲۲۷وَ اِنْ عَزَمُوا انتظار کرنا (جائز) ہے.پھر اگر (اس عرصہ میں صلح کے خیال کی طرف) لوٹ آئیں تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا (اور) الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۰۰۲۲۸ بار بار رحم کرنے والا ہے.اور اگر وہ طلاق کا فیصلہ کرلیں.تو اللہ بہت سننے والا (اور) بہت جاننے والا ہے.حلّ لُغات.اِیْلَاءٌ اٰلٰی یُؤْلِیْ اِیْلَاءً قسم کھانا.یہ اَلَاسے نکلا ہے جس کے معنے کسی کام میں کمی یا تاخیر کرنے کے ہیں.اور اِیْلَاءٌ قرآن کریم کے محاورہ میں اُس قسم کو کہتے ہیں جو اس بات پر کھائی جائے کہ مرد اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھے گا (مفردات) چونکہ اس قسم میں عورت کے حق کا اتلاف ہے اس لئے اسے اِیْلَاء کہا گیا.فَآءُ وْا فَاءَ یَفِیْ ءُ فَیْئًا لوٹ آیا.فَاءَ الْاَمْرَ اَیْ رَجَعَ اِلَیْہِ (اقرب) اس بات کی طرف لوٹ آیا.فَاءَ کالفظ نیک امور کی طرف لوٹنے کے متعلق استعمال ہوتا ہے.(مفردات) اصل میں اس کے معنے تعاون اور امداد باہمی کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے ہوتے ہیں.اور سایہ کو بھی فَيْء کہتے ہیںکیونکہ وہ
Page 350
سورج کے ساتھ ادھر سے اُدھر ہوتا رہتا ہے ان دونوں معنوں کو مدنظر رکھتے ہوئے فَاءَ بالعموم اچھے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے.تفسیر.ایلاء کے معنے قسم کے ہیں لیکن اصطلاحی طور پر کسی شخص کا قسم کھا کر اپنی بیوی سے علیٰحدگی اختیار کر لینا ایلاء کہلاتا ہے.عرب میں یہ رواج تھا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو طلاق تو نہ دیتے لیکن قسم کھا لیتے تھے کہ ہم ان سے تعلق نہیں رکھیں گے اور اس قسم کے ذریعہ وہ اپنے خیال میں بیوی کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتے تھے.کیونکہ ان کے خیال میں قسم کو پورا کرنے کی ذمہ داری خدا تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتی ہے اور بندوں کی ذمہ داری سے مقدم ہے.پس جب کہ خدا تعالیٰ کی قسم روک بن گئی تو ان کے خیال کے مطابق عورت کے حقوق کا ادا نہ کرنا کوئی گناہ نہ رہا.یہ گندہ خیال اب بھی دنیا میں موجود ہے.بلکہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم بیویوں سے تعلق نہیں رکھیں گے.لیکن انہیںطلاق بھی نہیں دیتے.اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر بیٹھے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسے چار مہینے کی مہلت دی جاتی ہے اس عرصہ میں وہ صلح کرلے توبہتر ورنہ جیساکہ اگلی آیت میں ہے پھر قاضی طلاق کافیصلہ کردےگا.اس آ یت میں اﷲ تعالیٰ نے عورت کو معلّقہ چھوڑنے کے خلاف فیصلہ فرمایا ہے.مر د زیادہ سے زیادہ مدت نکاح میںچار ماہ تک کے لئے عورت سے علیحدہ رہنے کا عہد کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص چار ما ہ سے زائدعرصہ کے لئے زائدعرصہ کے لئے قسم کھائے تو عورت کاحق ہے کہ خلع کرا لے.ایسی صورت میںطلاق واقعہ نہیں ہوتی.کیونکہ اس کا حکم آگے مذکور ہے.لیکن عورت کوخلع کاحق حاصل ہوجاتا ہے.اور اگر کوئی شخص تھوڑی تھوڑی مدت کے لئے ایلاء کرے مثلاً دس دن کےلئے ایلاء کیا اورپھر رجوع کیا.پھر دس دن کے لئے نیا ایلاء کیااور پھر رجوع کر لیا تب بھی اس کے لئے مجموعی طور پر چارماہ کی ہی مدت مقرر ہے.اگروہ چار ماہ کے بعد ایلاء کرےگا.تووہ ایلاء ناجائز ہو گا اورعورت علیحدگی کی حقدارہو گی.بعض لوگ عورت کودکھ دینے کے لئے تھوڑی تھوڑی مدت مقررکرتے رہتے ہیں تاکہ نہ چار ماہ ختم ہوں اور نہ عورت علیحدہ ہومگر ان کایہ خیال غلط ہے اس قسم کی ایلاء کی مدت بھی صرف چار ماہ ہی ہے.جب ایام قطع تعلق کا مجموعہ چار ماہ ہو جائے گا.تو لازماً عورت علیحدگی کی حق دارہو گی.فقہاء کااس آیت کے احکام کی تفصیلات میں اختلاف ہے.بعض کہتے ہیں کہ اگر مدت گزر جائے اور مرد عورت سے نہ مباشرت کرے اور نہ زبان سے رجوع کرے تو قاضی دونوں میں علیحدگی کروادےگا.یہ امام مالک کا قول ہے.لیکن امام ابو حنیفہ ؒکہتے ہیں کہ چار ماہ کے ختم ہونے سے پہلے رجوع ضروری ہے.اگر چار ماہ کے اندر رجوع نہ کرے تو اس مدت کے گزرنے کے بعد عورت کو خود بخود طلاق ہو جائے گی.
Page 351
افضل قول یہی ہے.لیکن محتاط امام مالکؒ کافتویٰ ہے امام شافعی ؒ اورامام احمد بن حنبل ؒ کے نزدیک چار ماہ گذرنے پراگر کوئی شخص رجوع نہ کرے تواسے قاضی مجبورکرے گا کہ رجوع کرے یاطلاق دے.یہ بھی قریباً امام مالکؒ کے قول سے ملتا ہے اگر مرد دونوں باتوںسے کوئی بھی نہ کرے گا.تو قاضی اس کی طرف سے طلاق دلا دے گا (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعة ، شرعی حدود متعلقہ احکام ایلاء).امام نخعی ؒ کا قول ہے کہ یہ رجوع پوشیدہ جائز نہیں نہ اشارہ سے بلکہ قول سے ہونا چاہیے.اور گواہوں کی موجودگی اس کے لئے ضروری ہے (کشّاف زیر آیت ھذا).غرض قرآن کریم عورت کو کَالْمُعَلّقَۃ چھوڑنے سے منع کرتا ہے.اور جو چھوڑے اسے مجبور کرتا ہے کہ یا صلح کرے یا اسے طلاق دے دے.غَفُوْرٌ کے لفظ سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بغیر کسی جائز عذر کے اس قسم کی قسم کھانا اور عورت کو دق کرنا گناہ کی بات ہے.تمہیں ایسے فعل سے توبہ کرنی چاہیے اور عورت کودق نہیں کرنا چاہیے.وَ اِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ میں بتایا کہ اگرمرد طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو اﷲبھی سننے والا اور جاننے وا لا ہے.سَمِيْعٌکے لفظ سے ڈرایا کہ اگر وہ اپنی بیوی سے نا انصا فی کر ےگا تو اسے یا د رکھنا چا ہیے کہ وہ اس کے بدنتائج سے بچ نہیں سکتاکیونکہ اللہ تعالیٰ اُس کی بیو ی کی فر یا د کو سننے وا لا ہے.اورعَلِيْمٌ میں بتا یا کہ جو خیالا ت تمہارے دلو ں کے اندر ہیںاللہ تعالیٰ ان کو بھی خو ب جا نتا ہے اور انہی کے مطابق تم سے معا ملہ کر ےگااس لئے تم اپنے معاملات میں ہو شیا ر رہو.تم دنیا کو تو دھوکا دے سکتے ہو مگر خدا تعالیٰ کو نہیں.چو نکہ اس جگہ عو رت سے حسن سلو ک کو حکم دیا ہے.اس لئے اگر کو ئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے حسن سلوک نہیں کر وںگا تو یہ قسم بھی اس پہلی قسم ہی کی طرح ہو گی جس کا ذکر لَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ۠ اَنْ تَبَرُّوْا وَ تَتَّقُوْا میں کیا گیا ہے.وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ١ؕ وَ لَا اور جن عورتوں کو طلاق مل جائے وہ تین (بار) حیض (آنے) تک اپنےآپ کو روکے رکھیں.اور اگر انہیں اللہ (پر) اور يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ روز آخرت پر ایمان ہے تو (انہیں معلوم رہے کہ) جو کچھ اللہ (تعالیٰ )نے ان کے رحموں میں پیدا کر رکھا ہے ان
Page 352
كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ١ؕ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ کےلئے اس کا چھپانا جائز نہیں.اور اگر ان کے خاوند باہمی اصلاح کا ارادہ کر لیں تو وہ اس (مدت) کے اندر (اندر ) بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا١ؕ وَ لَهُنَّ مِثْلُ ان کو( اپنی زوجیت میں) واپس لےلینے کے زیادہ حق دار ہیں.اور جس طرح ان( یعنی عورتوں پر )کچھ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ١۪ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ١ؕ ذمہ داریاںہیں (ویسے ہی )مطابق دستور انہیں بھی (کچھ حقوق) حاصل ہیں.ہاں مردوں کو ان پر ایک طرح کی وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌؒ۰۰۲۲۹ فوقیت حاصل ہے اور اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے.تفسیر.اب اللہ تعالیٰ طلاق کے مسائل بیان فرماتا ہے اور اس بارہ میں سب سے پہلی ہدایت یہ دیتا ہے کہ جن عورتوں کو اُن کے خاوند طلاق دے دیں.انہیں اپنے آپ کو تین قروء تک روکے رکھنا چاہیے.قُرُوْء سے کیا مُراد ہے؟اس بارہ میں اُمت محمدیہ میں دو گروہ پائے جاتے ہیں.خلفاء اربعہ یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ اِس سے حیض مُراد ہے.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور امام ابو حنیفہؒ کی بھی یہی رائے ہے(ابن کثیر ، مجمع البیان از طبری زیر آیت ھٰذا).لیکن حضرت عائشہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعی ؒ کہتے ہیں کہ اس سے طُہر مراد ہے.حضرت محی الدین ابنِ عربی ؒ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کودیکھا اور آپ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اہل عرب توقُرء سے حیض بھی مُراد لیتے ہیں اور طُہر بھی.اللہ تعالیٰ کا اس سے کیا منشاء ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے جو جواب دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں کو صحیح قرار دیا ہا ں ترجیح آپ نے طُہر کو دی.(فتو حا تِ مکیہ جلد ۴.با ب ۵۶۰صفحہ ۶۰۹،۶۱۰) عدّت کی حکمت با لکل و اضح ہے.اس عرصہ میں خا وند کو سو چنے اور غو ر کر نے کا کا فی وقت مل جا تاہے.اور اگر اس کے دل میںاپنی بیوی کی کچھ بھی محبت ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے.
Page 353
وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ میں عو رت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ حا ملہ ہو تو مرد کو بتا دے.کیو نکہ بسا اوقا ت ایسا ہو تا ہے کہ اگر عو رت حا ملہ ہو تو اس کی وجہ سے پھرآپس میں محبت قا ئم ہو جا تی ہے اور میا ں بیو ی میں صلح کی صو رت پیدا ہو جا تی ہے.وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ میں ذٰلِکَ کا اشا رہ مدت تر بُّص کی طر ف ہے.اوراللہ تعالیٰ نے بتا یا ہے کہ اگر عدت کے دوران خا وند اپنی عورت سے دوبا رہ تعلقا ت قا ئم کرنا چا ہے تو اس میں کسی کو روک نہیں بننا چا ہیے.اس ہدا یت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عا م طور پر عو رت کے رشتہ دار کہہ دیا کر تے ہیں کہ چو نکہ خا وند نے اپنی بیوی سے اچھا سلوک نہیں کیا اور اسے ایک دفعہ طلا ق دے دی ہے اس لئے اب ہم اس سے تعلق قا ئم رکھنے کے لئے تیا ر نہیں.اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ عو رت کے رشتہ داروں کو میا ںبیوی کے تعلقا ت میں روک نہیں بننا چا ہیے.اگر خاوند اپنی غلطی کو محسو س کر تے ہوئے رجو ع کر ناچاہتا ہے تو وہ کسی اور کی نسبت اس عو رت کا زیا دہ حق دار ہے اور وہ عدّت میں اپنی عو رت کو وا پس لوٹا سکتا ہے.پھر وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ میں عا م قا نو ن بتا یا کہ مر دوں اور عو رتو ں کے حقوق بحیثیت انسان ہونے کے بر ا بر ہیں جس طرح عو رتو ں کے لئے ضر وری ہے کہ وہ مر دوں کے حقو ق کا خیا ل رکھیں اسی طر ح مر دوں کے لئے بھی ضر و ری ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق ادا کر یںاور اس بارہ میں کسی قسم کا ناواجب پہلو اختیار نہ کریں.رسو ل کر یم صلی اللہ علیہ و سلم کی بعثت سے پہلے عو رتوں کے کو ئی حقو ق تسلیم ہی نہیں کئے جا تے تھے بلکہ انہیں مالوں اور جا ئیدادوں کی طر ح ایک منتقل ہونے والا ورثہ خیا ل کیا جا تا تھا.اور اُن کی پیدا ئش کو صر ف مر د کی خو شی کا مو جب قرا ر دیا جا تا تھا حتّٰی کہ مسیحی جو اپنے آ پ کو حقو قِ نِسوا ں کے بڑے حا می کہتے ہیں اُن کے پا ک نوشتوں میں بھی عورت کی نسبت لکھا تھا.’’البتہ مرد کو اپنا سرڈھا نکنا نہ چا ہیے کیو نکہ وہ خدا کی صو رت اور اُس کا جلا ل ہے مگر عورت مردکا جلا ل ہے.‘‘ (کر نتھیوں باب ۱۱ آ یت۷) اسی طر ح لکھا تھا.’’ اور میں اجا زت نہیں دیتا کہ عو رت سکھا ئے‘‘ (تمطا ؤس با ب ۲آ یت ۱۲) صر ف اسلا م ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں عو رتوں کی انسا نیت کو نما یا ں کر کے دکھا یا.اور رسول کر یم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم ہی وہ پہلے انسا ن ہیں جنہو ں نے عو رتوں کے بلحاظ انسا نیت بر ابر کے حقوق قا ئم کئے.اور
Page 354
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ کی تفسیر لوگوں کے اچھی طر ح ذہن نشین کی.آ پ کے کلا م میں عو رتو ں کے ساتھ حسن سلو ک اور ان کے حقو ق اور ان کی قا بلیتوں کے متعلق جس قدر ارشا دا ت پا ئے جا تے ہیں ان کا دسواں حصّہ بھی کسی اور مذہبی پیشوا کی تعلیم میں نہیں ملتا.آ ج سا ری دنیا میں یہ شو ر مچ رہا ہے کہ عو رتوں کوان کے حقوق دینے چاہئیں اور بعض مغر ب زدہ نو جوا ن تو یہا ں تک کہہ دیتے ہیں کہ عو رتوں کو حقوق عیسا ئیت نے ہی دئیے ہیں حا لا نکہ عورتوں کے حقوق کے سلسلہ میں اسلا م نے جو وسیع تعلیم دی ہے عیسا ئیت کی تعلیم اس کے پا سنگ بھی نہیں.عر بو ں میں رواج تھا کہ ورثہ میں اپنی ما ؤں کو بھی تقسیم کر لیتے تھے.مگر اسلام نے خو د عو رت کو وا رث قرا ر دیا.بیوی کو خا وند کا.بہن کو با پ کا اور بعض صورتوں میں بہن کو بھا ئی کا بھی.غرض فر ما یا وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ یعنی انسانی حقوق کا جہا ں تک سوا ل ہے عورتوںکو بھی ویسا ہی حق حاصل ہے جیسے مر دوں کو.ان دونوں میں کو ئی فر ق نہیں.اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں اور عو رتو ں کو یکساں احکا م دئیے ہیں اسی طر ح انعا ما ت میں بھی انہیں یکسا ں شر یک قرار دیا ہے.اور جن نعما ء کے مر د مستحق ہوںگےاسلا می تعلیم کے ما تحت قیا مت کے دن وہی انعا ما ت عو رتوں کو بھی ملیں گے.غر ض اللہ تعالیٰ نے نہ اس دنیا میں ان کی کوئی حق تلفی کی ہے اور نہ اگلے جہان میں انہیں کسی انعام سے محروم رکھاہے.ہاں آپ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ یعنی حقوق کے لحاظ سے تو مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں لیکن انتظامی لحاظ سے مردوں کو عورتوں پر ایک حقِ فوقیت حاصل ہے.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ایک مجسٹریٹ انسان ہونے کے لحاظ سے تو عام انسانوں جیسے حقوق رکھتا ہے اور جس طرح ایک ادنیٰ سے ادنیٰ انسان کو بھی ظلم اور تعدّی کی اجازت نہیں اُسی طرح مجسٹریٹ کو بھی نہیں.مگر پھر بھی وہ بحیثیت مجسٹریٹ اپنے ماتحتوں پر فوقیت رکھتاہے.اور اُسے قانون کے مطابق دوسروں کو سزا دینے کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں.اِسی طرح تمدنی اور مذہبی معاملات میں مرد و عورت دونوں کے حقوق برابر ہیں.لیکن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قوّام ہونے کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے لیکن دوسری طرف اس نے عورتوں کو استمالتِ قلب کی ایسی طاقت دےدی ہے جس کی وجہ سے وہ بسا اوقات مردوں پر غالب آجاتی ہیں.بنگالہ کی جادوگر عورتیں تو جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے مردوں پر جادو سا کر دیتی ہیں.پس جہاں مرد کو عورت پر ایک رنگ میں فوقیت دی گئی ہے.وہاں عورت کو استمالتِ قلب کی طاقت عطا فرما کرمرد پر غلبہ دے دیا گیا ہے.جس کی وجہ سے بسا اوقات عورتیں مردوں پر اس طرح حکومت کرتی ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سب کاروبار انہیں کے ہاتھ میں ہے.دراصل ہر شخص کی الگ الگ رنگ کی حکومت ہوتی ہے.جہاں تک احکام شرعی اور نظام کے قیام کا
Page 355
سوال ہے.اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دے دی ہے مثلاًشریعت کا یہ حکم ہے کہ کوئی لڑکی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیںکر سکتی(بخاری کتاب النکاح باب من قال لا نکاح الا بولیّ).یہ حکم ایسا ہے جو اپنے اندر بہت بڑےفوائد رکھتا ہے.یورپ میں ہزاروں مثالیںایسی پائی جاتی ہیںکہ بعض لوگ دھوکے باز اور فریبی تھے مگر اس وجہ سے کہ وہ خوش و ضع نوجوان تھے انہوں نے بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیں اور بعد میں کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہوئیں.لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ رشتہ کی تجویز کے وقت باپ غور کرتا ہے والدہ غور کرتی ہے.بھائی سوچتے ہیں.رشتہ دار تحقیق کرتے ہیں اور اس طرح جو بات طے ہوتی ہے وہ بالعموم ان نقائص سے پاک ہوتی ہے جو یورپ میں نظر آتے ہیں.یورپ میں تو یہ نقص اس قدر زیادہ ہے کہ جرمنی کے سابق شہنشاہ کی بہن نے اسی ناواقفی کی وجہ سے ایک باورچی سے شادی کرلی ا س کی وضع قطع اچھی تھی اور اس نے مشہوریہ کر دیا تھا کہ وہ روس کا شہزادہ ہے جب شادی ہو گئی توبعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کہیں باورچی کا کام کیا کرتا تھا.یہ واقعات ہیں جو یورپ میں کثرت سے ہوتے رہتے ہیں ان واقعات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مردوں کے قو ام ہونے کے متعلق جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے.شر یعت کا اس سے یہ منشا نہیں کہ عورتوں پر ظلم ہو یا ان کی کوئی حق تلفی ہو بلکہ شر یعت کا اس امتیا ز سے یہ منشا ہے کہ جن با تو ں میں عو رتوں کو نقصا ن پہنچ سکتا ہےان میں عو رتوں کو نقصا ن سے محفوظ رکھا جا ئے.اسی وجہ سے جن با تو ں میں عو رتو ں کو کو ئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ان میں ان کا حق خدا تعالیٰ نے خو د ہی انہیں دے دیا ہے.پس قر آ ن کر یم نے جوکچھ کہا ہے وہ اپنے اندر بہت بڑی حکمتیں اور مصا لح رکھتا ہے.اگر دنیا ان کے خلا ف عمل کر رہی ہے تو وہ کئی قسم کے نقصا نا ت بھی بر دا شت کر رہی ہے جو اس با ت کا ثبو ت ہیں کہ اسلا م کے خلا ف عمل پیرا ہو نا کبھی نیک نتا ئج کا حامل نہیں ہو سکتا.آ خر میںوَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ فر ما کر اس طرف تو جہ دلا ئی کہ یاد رکھو! عو رتوں پر جو فو قیت ہم نے تمہیں دی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس سے نا جا ئز فا ئد ہ اٹھا ؤ.اور ان کے حقو ق کو پا ما ل کر ناشر وع کر دو.دیکھو !تم پر بھی ایک حا کم ہے جوعز یز ہے.یعنی اصل حکو مت خدا تعالیٰ کی ہے اس لئے چا ہیے کہ مر د اس حکو مت سے نا جا ئز فائدہ نہ اٹھائے.اور حکیم کہہ کر اس طرف تو جہ دلا ئی کہ ضبط و نظم کے معا ملا ت میں جو اختیا ر ہم نے مر دوں کو دیا ہے.یہ سرا سر حکمت پر مبنی ہے ورنہ گھر وں کا امن بر با د ہو جاتا.چو نکہ میاں بیوی نے مل کر رہنا ہو تا ہے اور نظا م اس وقت تک قا ئم نہیں رہ سکتا جب تک کہ ایک کو فو قیت نہ دی جا ئے اس لئے یہ فو قیت مر د کو دی گئی ہے اور اس کی ایک اور و جہ اللہ تعالیٰ
Page 356
نے دو سر ی جگہ یہ بیا ن فر ما ئی ہے کہ چو نکہ مر د اپنا روپیہ عو رتوں پر خرچ کر تے ہیں اس لئے انتظا می امور میں انہیں عورتوں پرفو قیت حا صل ہے(النساء: ۳۵).اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ١۪ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ ایسی طلاق (جس میں رجوع ہو سکے )دو دفعہ (ہو سکتی) ہے.پھر (یا تو) مناسب طور پر روک لینا ہو گا یا حسن سلوک بِاِحْسَانٍ١ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ کے ساتھ رخصت کردینا ہوگا.اور تمہارے لئے اس (مال )کا جو تم انہیں پہلے دے چکے ہو کوئی حصہ بھی (واپس) لینا شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ١ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ جائز نہیںسوائے اس (صورت) کے کہ ان (دونوں )کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی( مقررہ کردہ) حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ١ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا گے.سو اگر تمہیں( ملت اسلامیہ یا اسلام پر ایمان رکھنے والی حکو مت کو یہ) اندیشہ ہو کہ وہ( دونوں) اللہ کی افْتَدَتْ بِهٖ١ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا١ۚ وَ مَنْ ( مقررکردہ) حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے.تو وہ (یعنی عورت )جو کچھ بطور فدیہ دے اس کے بارہ میں ان يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۰۰۲۳۰ ( دونوں میں سےکسی )کو کوئی گناہ نہ ہو گا.یہ اللہ کی (مقرر کردہ )حدیں ہیں اس لئے تم ان سے باہر نہ نکلو.اور جو اللہ کی( مقرر کردہ )حدوں سے باہر نکل جائیں تو (سمجھ لو کہ) وہی لوگ (اصل )ظالم ہیں.تفسیر.اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ سے مرا د یہ ہے کہ ایسی طلا ق جس میں خا وند کو رجوع کا حق حا صل ہے صر ف دو دفعہ ہی ہو سکتی ہے.یہ نہیں کہ عو رت کو تنگ کر نے کے لئے اسے بار بار طلا ق دیتا رہے.اور جب عدت ختم ہو نے کا وقت قر یب آ ئے تو رجوع کر لے.احکا م دینیہ کے سا تھ یہ ایک نا پا ک تمسخر ہے جس کی اسلا م ہر گز اجا زت
Page 357
نہیں دیتا.احا دیث میں صر احتاًذکر آ تا ہے کہ رسو ل کر یم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زما نہ میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ لَا اُطَلِّقُکِ اَبَدًا وَلَااٰوِیْکِ اَبَدًا یعنی نہ تو میں تجھے کبھی طلا ق دو ںگا اور نہ اپنے گھر میں بسا ؤںگا.عورت نے پو چھا.وَکَیْفَ ذٰلِکَ یہ کس طر ح ہو سکتا ہے؟ اس پر اس نے کہا اُطَلِّقُ حَتّٰی اِذَا اَتٰی اَجَلُکِ رَاجَعْتُکِ میں تجھے طلا ق دوںگا اور جب تیر ی عدت ختم ہو نے کے قر یب پہنچے گی تو رجوع کر لوںگا.اگلی دفعہ پھر ایسا کروںگا اور پھر رجوع کر لوں گا.اس طرح نہ تجھے بساؤ ںگا اور نہ علیحدہ ہونے دو ںگا.وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اُس نے اس واقعہ کا آپ سے ذکر کیا.اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ یعنی وہ طلاق جس میں مرد کو رجوع کا حق حاصل ہے صرف دو دفعہ ہے اس سے زیادہ نہیں (ترمذی کتاب الطلاق و اللعان باب نزول قولہ الطلاق مرَّتٰن) اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دو طلاقوں تک تومرد کو رجو ع کا حق حاصل رہتا ہے لیکن تیسری طلاق کے بعد اُسے رجوع کاکوئی حق نہیں رہتا.اور یہ دوطلاقیں بھی بیک وقت نہیں دی جا سکتیں بلکہ یکے بعد دیگرے دی جاتی ہیں جس کی طرف مَرَّ تٰنِ کا لفظ اشارہ کرتا ہے جس کے معنے مَرَّۃً بَعْدَ مَرَّۃٍکے ہیں.یعنی ایک ہی دفعہ طلاقیں نہ دی جائیں بلکہ باری باری دی جائیںاور ہر طلاق کی مدت جیسا کہ اوپر کی آیت میں گذرچکاہے تیںقروء ہے خواہ وہ ہر مہینے میں ایک طلاق دے یا شروع میں ایک دفعہ دے.اس سے طلاق کے لحاظ سے کو ئی فرق نہیں پڑتا.فقہاء نے ہر مہینے طلاق دینے کی طرف اس لئے توجہ دلائی ہے کہ اس طرح بار بار انسان کو رجوع کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع از کاشانی زیر عنوان کتاب الطلاق ).میرے نزدیک خواہ انسان ایک دفعہ طلاق دے یا ہر مہینے طلاق دے وہ ایک ہی طلاق سمجھی جائےگی.اور عدت گذرنے کے بعد پھر خاوند نکاح کرسکے گا.اِس قسم کی طلاقیں صرف دوجائز ہیں یعنی طلاق دینا اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لینا.اگر دو ہو جائیں تو اس کے بعد پھر اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دے تو ایسے شخص کے لئے اس عورت سے دوبارہ نکاح جائزنہیں جب تک کہ وہ باقاعدہ اور شرعی نکاح دوسرے شخص سے نہ کر چکی ہو جو حقیقی نکاح ہے حلالہ نہیں.کیونکہ حلالہ کا وجود اسلام میں نہیں ملتا.غرض اَلطَّلَاقُ سے مُراد وہ طلاق ہے جس کی عدت گذر چکی ہے وہ طلاق نہیں جس پر عدت نہ گذری ہو.اس میں رجوع ہو سکتا ہے جس پر عدت گذرچکی ہو اس میں دو دفعہ نکاح ہوسکتا ہے.تیسری دفعہ نہیں.بیشک بعض حدیثیں اور بعض فقہا ء کے اقوال اس کے خلاف نظر آتے ہیں.لیکن قرآن کریم کے الفاظ
Page 358
َلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ بالکل واضح ہیں اور اس سے پہلی آیت وَ الْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ١ؕ وَ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ١ؕ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْۤا اِصْلَاحًا.واضح کرتی ہے کہ زمانہ طلاق تین قروء تک جاتا ہے اس عرصہ میں انسان بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے اور اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ کے چند آیات بعد کی آیت وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ(البقرة:۲۳۳)بتاتی ہے.کہ طلاق کی مدت گذر جانے کے بعد خاوند دوبارہ نکاح کر سکتا ہے.درمیانی آیت اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ اس پہلی قسم کی طلاق کی طرف اشارہ کرتی ہے اورپہلی قسم کی طلاق یہی ہے کہ تین قروء تک رجوع جائز ہے اور تین قروء کے بعد نکاح جائز ہے.غرض آیت اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ بتاتی ہے کہ ایسی طلاق دو دفعہ ہو سکتی ہے جس کے صاف معنے یہ ہیںکہ طلاق کے بعد عدت گذر جانے کی صورت میں خاوند کو دو دفعہ دوبارہ نکاح کا حق حاصل ہے.ایسے دو واقعات کے بعد اگر پھر انسان طلاق دےدے تو اس کو نکاح کا حق حاصل نہیں رہتا بلکہ اسے عرصہ مدت میں رجوع کا بھی حق حاصل نہیں.پھر یہ حق اس کو تبھی حاصل ہو گا جبکہ وہ عورت کسی دوسرے شخص سے باقاعدہ نکاح کرے اور وہ مرد اس کو کسی وجہ سے طلاق دےدے.فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ میں بتایا کہ ان دو طلاقوں کے بعد یا تو عورت کو معروف طریق کے مطابق اپنے گھروں میں بسا لو اوریا پھر حسنِ سلوک کے ساتھ رخصت کر دو.تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی بھی ایک تشریح احادیث میں بیان کی گئی ہے.چنانچہ ابنِؔ ابی حاتم نے ابی رزین سے روایت کی ہے کہ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰی النَّبِیِّ ﷺ فَقَالَ یَا رَسُوْلَ اﷲ ! اَرَءَیْتَ قَوْلَ ﷲِ الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَاِمْسَاکٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٌ بِاَحْسَانٍ اَیْنَ الثَالِثَۃُ قَالَ التَّسْرِیْحُ بِاَحْسَانٍ.یعنی رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص آیا.اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اﷲ! دو طلاقیں توقرآن میں بیان ہوئی ہیں.تیسری کہاں سے آئی ؟ آپ نے فرمایا.اَوْتَسْرِیْـحٌ بِاِحْسَانٍ جو آیا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تَسْرِیْـحٌ بِاِحْسَانٍ کو آپ نے تیسری طلاق قرار دیا ہے(تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم سورۃ البقرۃ زیر آیت ھٰذا).اس جگہ احسان کا لفظ رکھ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ عورت کو رخصت کرتے وقت اس کے ساتھ احسان کامعاملہ کرنا چاہیے.مثلاً اس کے حق سے زائد مال اسے دےدیا جائے اور اسے عزت کے ساتھ روانہ کیا جائے.بعض صحابہ ؓ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کوطلاق دی تو انہیں دس دس ہزار روپیہ تک دے دیا.پھر فرمایا
Page 359
وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَاْخُذُوْامِمَّااٰتَیْتُمُوْھُنَّ شَیْئًا.تمہارے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اگر کوئی مال یا جائیداد تم انہیں دے چکے ہو تو طلاق کے بعد ان سے واپس لے لو.یہ آیت بالصراحت بتاتی ہے کہ طلاق کے بعد عورت سے زیورات اور پارچات وغیرہ واپس نہیں لئے جا سکتے.نہ مال واپس لیا جا سکتا ہے.نہ کوئی جائداد جو اسے دی جا چکی ہو واپس لی جا سکتی ہے بلکہ مرد اگرمہر ادا نہ کر چکا ہو تو طلاق کی صورت میں وہ مہر بھی اسے ادا کرنا پڑےگا.لیکن اسکے بعد ایک استثنیٰ رکھا ہے اورکہا ہے کہ اگر وہ صورت پیدا ہو تو پھر جائز ہے.چنانچہ فرمایا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ.سوائے اس کے کہ ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے یعنی مرد عورت کے حقوق ادا نہ کر سکے گا.اورعورت مرد کے حقوق ادا نہ کر سکے گی.اس صورت میں اس کا حکم اور ہے.جو فَاِنْ خِفْتُمْ سے شروع ہوتا ہے.چنانچہ فرماتا ہے.فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ١ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ.یعنی اس صورت میں اگر تمہاری رائے بھی یہی ہو کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے یعنی قضا نے بھی دیکھ لیا کہ فی الواقعہ دونوں کا قصور ہے صرف مرد ہی کا قصور نہیں ہے.بلکہ عورت بھی قصور وار ہے تو اس صورت میں اگر عورت سے کچھ دلوا کر ان میں جدائی کروا دی جائے جسے اصطلاحاً خلع کہتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہو گا.یہ ایک عجیب با ت ہے کہ اس آ یت میں تَاْخُذُوْا کی ضمیر اور طر ف گئی ہے اورخِفْتُمْ کی ضمیر اورطرف حا لا نکہ جملہ ایک ہی ہے.یعنی تَاْخُذُوْا سے مرا د خا وند ہیں.اور خِفْتُمْ سے مراد محکمہ قضا ء سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں (رازی).اسے اصطلا ح میں انتشار ضما ئر کہتے ہیں.اورنحوی اسے جا ئز قرا ر دیتے ہیں.غر ض فَاِنْ خِفْتُمْ میں بتا یا کہ اگر حکا م اس با ت کا فیصلہ کر یں کہ........عو رت راضی نہیں اور اس کی نا رضا مندی کی وجہ سے مر د بھی عدل نہ رکھ سکے گا تو عو رت اگر کچھ دینا چا ہے تو مرد کو اجا زت ہے کہ لےکراسے طلا ق دے دے.چنا نچہ اس کے متعلق احا دیث میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے زما نہ کے ایک وا قعہ کا ذکر کیا گیا ہے.جس سے اس مسئلہ پر روشنی پڑ تی ہے.ابن ما جہ اور نسا ئی میں آ تا ہے کہ ثابت بن قیس بن شما س کی بیوی( یعنی عبد اللہ بن ابَیّ بن سلول کی بیٹی) رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی خد مت میں حا ضر ہو ئی.اور اس نے عر ض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے اپنے خا وند سے اس قدر نفر ت ہے کہ اگر وہ مجھ سے حسن سلو ک بھی کر ے.تب بھی میں اس کی طر ف تو جہ نہیں کر سکتی اور سو ائے اس نفر ت کے مجھے اس سے اور کو ئی شکا یت نہیں.رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خا وند کو بلا یا.اور اس سے دریافت فر ما یا کہ تم نے اسے کچھ دیا ہوا ہے اس نے عرض کیا کہ ایک با غ ہے جو میں نے اسے دیا ہوا ہے.رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فر ما یا اَتَرُدِّیْنَ عَلَیْہِ حَدِ یْقَتَہٗ کہ کیا تو اس کا با غ اسے وا پس کر سکتی ہے؟ قَا لَتْ
Page 360
نَعَمْ اس نے کہا ہاں! یا رسول اللہ!میں با غ وا پس کر دوںگی.فَاَمَرَہٗ رَسُوْلُ اللّٰہِ اَنْ یَّاْ خُذَ الْحَدِ یْقَۃَ وَلَا یَزِ یْدَ عَلَیْھَا (ابن ماجہ باب الطلاق باب المختلعۃ تأخذ ما اعطاھا...نسائی کتاب الطلاق باب ما جاء فی الخلع) اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ اس سے اپنا با غ واپس لے لے اور اس سے زیا دہ کچھ نہ لے.دوسر ی روایت میں ذکر آ تا ہے کہ اس عورت نے کہا یا رسو ل اللہ !میں تو زیا دہ دینے کے لئے بھی تیا ر ہوں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فر ما یا.اَمَّا الزِّیَا دَۃُ فَلَا.کہ زیا دہ ہر گز نہیں.بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ حبیبہؔ بنت سہیل کا وا قعہ ہے.بہر حا ل رسو ل کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ با غ اس سے وا پس کروا دیا اور عورت کو طلا ق دلوا دی اور مر د کو اس سے زیا دہ لینے کی اجازت نہ دی.اس سے معلو م ہوا کہ صرف خا وند کاما ل اسے واپس دلوا یا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں.اس جگہ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا دو وجو ہ کی بنا پر کہاگیا ہے.اوّل اس لئے کہ اس سے پہلے لَا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَاخُذُ وْامِمَّا اٰتَیْتُمُوْ ھُنَّ شَیْئًا فر ما کر عو رت سے ما ل لینا گنا ہ قرار دیا تھا.پس چو نکہ یہ شبہ پڑتا تھا کہ کہیں اس صورت میں بھی ما ل لینا گنا ہ نہ ہو.اس لئے فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فرما کر اس شک کو دور کر دیا اور بتلا دیا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں.دوسرے فَلَا جُنَاحَ عَلَیْھِمَااس لئےفر ما یا کہ عور ت کا کچھ دےکر مرد سے آزاد ہونااس کے جدا ئی کے شو ق پر دلا لت کر تا ہے اور یہ گنا ہ ہے.جیسا کہ ابن جر یر نے ثوبا ن سے روا یت کی ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اَيُّ مَا امْرَ أَۃٍ سَأَ لَتْ زَوْجَھَا الطَّلَا قَ مِنْ غَیْرِ بَأْ سٍ حَرَّمَ اللّٰہُ عَلَیْھَا رَائِـحَۃَ الْجَنَّۃِ (تفسیر طبری زیر آیت ھٰذا ) یعنی جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے اپنے خا وند سے طلاق ما نگے.اس پر جنت کی خوشبو حرا م ہے.سو فر ما یا کہ اگر کو ئی حقیقی مجبو ری پیش آجا ئے تو اس صورت میں اس کی درخواست تفریق موجب گناہ نہیں ہوگی اسی طرح مرد کا عورت سے کچھ روپیہ لے کر چھو ڑنا اس کے لا لچ پر دلا لت کر تا ہے اور یہ بھی گنا ہ ہے.پس چو نکہ دونوں طرف گنا ہ کا شبہ ہو سکتا تھا.اس لئے بتا یا کہ قا ضی کی تحقیق کے بعد اس طر یق پر جدا ئی منا سب سمجھی جائے اور ایک تیسرا شخص فیصلہ کر دے کہ یہی طر یق منا سب ہے تو پھر دونوں کو کو ئی گنا ہ نہیں ہو گا.تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا.فر ماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کر دہ حد یں ہیں اور تمہا را فرض ہے کہ تم ان حدود سے اپنا قد م باہر مت رکھو.مگر افسوس ہے کہ مسلما نوں نے اس حکم کی یہا ں تک خلا ف ورزی کی کہ انہو ں نے کہہ دیا کہ اگر ایک مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں بھی دے دی جا ئیں.تب بھی طلا ق بتّہ وا قع ہو جا تی ہے.حا لا نکہ یہ سوا ل خو د رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کی خد مت میں پیش ہوا اور آ پ سے پو چھا گیا کہ کیا یہ ایک ہی طلا ق سمجھی
Page 361
جا ئےگی؟ تو آ پؐنے فر ما یا.یہ ایک ہی طلا ق ہے.چنانچہ حضرت ابن عبا س رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ طَلَّقَ رَکَا نَۃُ ثَلَاثًا فِیْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزَنَ عَلَیْہِ حُزْنًا شَدِ یْدًا فَسَأَ لَہٗ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ کَیْفَ طَلَّقْتَھَا قَالَ طَلَّقْتُھَا ثَلَاثًا فِیْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ اِنَّمَا تِلْکَ طَلْقَۃٌ وَا حِدَۃٌ فَا رْ تَجِعْھَا.(تفسیر مظہری سورۃ البقرۃ زیر آیت ھٰذا) یعنی ایک شخص رکا نہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں تین طلا قیں دے دیں اس کے بعد رکانہ کو اپنے اس فعل پر شدید صدمہ محسوس ہواجب یہ معا ملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سا منے پیش ہوا تو آپ نے دریا فت فر ما یا کہ تو نے اپنی بیوی کو کس طر ح طلا ق دی تھی؟ اس نے کہا.میں نے اسے ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دی تھیں.آپؐنے فر ما یا.یہ ایک ہی طلا ق ہے.اس لئے تم رجو ع کر لو.اسی طر ح نسا ئی میں محمود بن لبید سے روا یت ہے کہ اُخْبِرَرَسُوْلُ اللّٰہِ صَلّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَ أَ تَہٗ ثَلَاثَ تَطْلِیْقَا تٍ جَمِیْعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَا لَ اَ یُلْعَبُ بِکِتَا بِ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ وَاَنَا بَیْنَ اَظْھُرِکُمْ (نسائی کتاب الطلاق باب الثلاث المجموعۃ و فیہ من التغلیظ) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ہی دفعہ تین طلا قیں دے دی ہیں.اس پر رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نا را ضگی کا اظہار کیا اور فرمایا.ابھی تو میں تم میں مو جو د ہوں.کیا میری موجودگی میں وہ اللہ تعالیٰ کی کتا ب سے کھیلتا ہے.اسی طر ح حضرت ابن عباسؓ سے روا یت ہے کہ کَانَ الطَّلَاقُ عَلیٰ عَھْدِ رَسُوْلِ اللّٰہ صَلّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَ اَبِیْ بَکْرٍ وَ سَنَتَیْنِ مِنْ خِلَا فَۃِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَا ثِ وَ احِدَۃً فَقَا لَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّا بِ اِنَّ النَّا سَ قَدِاسْتَعْجَلُوْا فِیْ اَمْرٍ کَانَتْ لَھُمْ فِیْہِ اَنَاۃٌ فَلَوْ اَمْضَیْنَاہُ عَلَیْھِمْ فَاَمْضَاہُ عَلَیْھِمْ(مسلم کتاب الطلاق با ب طلا ق الثلاث) یعنی آنحضر ت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور حضرت ابو بکر ؓ کی خلا فت کے زما نہ میں اور حضرت عمرؓ کی خلا فت کے ابتدائی دو سال تک ایک وقت میں تین طلا قیں ایک ہی طلا ق تسلیم کی جا تی تھی.لیکن حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر کہ لوگ طلا قوں کو ایک معمولی با ت سمجھنے لگ گئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسے معا ملہ میں جس میں انہیں بہت غور اور سوچ بچا ر سے کا م لینے کا حکم تھا جلد بازی شر وع کر دی ہے وقتی طو رپریہ فیصلہ فر ما دیا کہ آ ئندہ اگر کسی نے اکھٹی تین طلاقیں دیں تو اس کی تین طلا قیںہی متصور ہوںگی.اما م ابن قیم نے اعلا م المو قعین جلد ۲ صفحہ ۲۴ تا ۲۶ میں اس مسئلہ کو وضا حت سے بیا ن کیا ہے.بد قسمتی سے ہما رے ملک میں بھی اسلا می تعلیم سے نا وا قفیت کی وجہ سے یہ رواج ہے کہ معمو لی معمولی جھگڑوں پر لو گ اپنی بیویوں سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں تین طلا ق.تمہیں تین ہزار طلا ق.تمہیں تین کڑور طلاق.تمہیںتین ارب طلاق.
Page 362
حا لا نکہ اسلام نے اس بیو قو فی کی اجا زت نہیں دی.اور پھر آج کل کے وہ لوگ جو شر یعت کے پورے واقف نہیں کہہ دیتے ہیں کہ تین دفعہ یکد م طلا ق دینے کے بعدعورت سے دوبارہ نکا ح نہیں ہو سکتا.حا لا نکہ یہ طلا ق شر عی لحا ظ سے ایک ہی طلا ق ہے اور عدت گزرنے کے بعد عورت سے دوبا رہ نکا ح ہو سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے بتا یا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب اس قسم کے واقعات کثرت سے ہونے لگے تو آ پ نے فر ما یا کہ اب اگر کو ئی شخص اپنی بیوی کو بیک وقت ایک سے زیا دہ طلا قیں دےگا تو میں سزا کے طور پر اس کی بیوی کو اس پر نا جا ئز قرار دے دوںگا.جب آ پ پر یہ سوا ل ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے تو ایسا حکم نہیں دیا.پھر آ پ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فر ما یا.رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا یہ منشاء تھاکہ اس قسم کی طلا قیں رک جا ئیں.مگر چو نکہ تم لوگ اس قسم کی طلاق دینے سے رکتے نہیں اس لئے میں سزا کے طور پر اس قسم کی طلا ق کو جا ئز قرار دے دوں گا.چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آ پ کا ایسا کرنا ایک وقتی مصلحت کے ما تحت تھا اور صرف سزا کے طورپر تھا مستقل حکم کے طور پر نہیں تھا.بہر حا ل طلا ق ایک ایسی چیز ہے جسے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اَبْغَضُ الْحَلَال قرار دیا ہے.یعنی جائز اور حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مکر وہ اور نا پسندیدہ چیز.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیوی زند گی میں انسان کے لئے جو چیزیں ضروری اور لا زمی ہیں اور جن کے ذریعہ انسا ن آ رام اور سکینت حا صل کر سکتا ہے وہ میاںبیوی کے تعلقات ہیں.میا ں بیوی کے تعلقات سے جو سکون اور آ رام انسا ن کو حاصل ہو تا ہے وہ اسے اور کسی ذریعہ سے حا صل نہیں ہو سکتا.قر آن کر یم میں اللہ تعالیٰ نے ان وجودوں کو ایک دوسرے کے لئے مودت اور رحمت کا موجب قرار دیا ہے.اسی طر ح با ئیبل میں آ تا ہے اللہ تعالیٰ نے آ دم کے لئے حوّا پیدا کی تا کہ وہ آ دم کے لئے آ رام اور سکون کاموجب ہو.یعنی حوّا کے بغیر آ دم کے لئے تسکین اور آ رام کی صورت اور کوئی نہ تھی.لیکن یہی دو وجود جو ایک دوسرے کے لئے تسکین اورآرام اور را حت کا مو جب ہیں کبھی کبھی انہیں لڑا ئی اور جھگڑے کا مو جب بنا لیا جا تا ہے اور راحت اور سکون کی بجا ئے انسا ن کے لئے اس کا مد ّمقا بل یعنی خا وند کے لئے بیوی اور بیوی کے لئے خا وند دنیا میں سب سے زیا دہ تکلیف دینے کامو جب بن جا تا ہے.ہزاروں خا وند ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے لئے بدترین عذاب ہو تے ہیں.اور ہزاروں بیو یا ں ایسی ہیں جو اپنے خا وندوں کے لئے بد ترین عذاب ہو تی ہیں.ایسے مواقع کے لئے اسلا م کا حکم ہے کہ مر د عورت کو طلاق دے دے یا عورت مرد سے خلع کر الے.لیکن طلا ق اور خلع سے پہلے اسلا م نے کچھ احکا م بیان کئے ہیں جن کو مدّنظر رکھنا مر د اور عورت اور قاضیوں کا فر ض قرا ر دیا گیا ہے تا کہ طلا ق یا خلع عا م نہ ہو جا ئے.رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں.اِنَّ اَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَاللّٰہِ الطَّلَاقُ
Page 363
(تفسیر لما تریدی (تأویلات أھل السنۃ) سورۃ الطلاق الآیات ۲ تا ۸ )یعنی حلال چیزوں میں سے سب سے زیا دہ ناپسندیدہ چیز خدا تعا لیٰ کے نزدیک طلاق ہے.جب طلاق حلال چیزوں میں سے سب سے زیا دہ نا پسندیدہ ہے تو ایک مو من جس کے دل میںاللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ اس چیز کے کس طرح قریب جا سکتا ہے جس کے متعلق وہ سمجھتا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت نا پسند ہے، ہر کا م جو جا ئز ہے ضروری نہیں کہ اسے کیا بھی جا ئے.ہر شخص جا نتا ہے کہ بنا رس.کلکتہ.مدراس یا بمبئی وغیرہ جانا حلال ہے لیکن کتنے ہیں جو ان جگہوںمیں گئے ہیں.اگر حلال کے یہی معنے ہیں کہ اسے ضرور کیا جائے توپھر تو یہ ہو نا چا ہیے تھا کہ جن لو گوں کے پا س ان شہروں میں جا نے کے لئے روپیہ نہ تھا.وہ اپنی جائیدادیں بیچ ڈالتے اور اس حلال کا م کوضرور سر انجا م دیتے لیکن لو گوں کا اس پر عمل نہ کر نا بتاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کو جو بات حلال ہے ضروری نہیں کہ اس پر عمل بھی کیا جا ئے بلکہ منا سب مو قعہ اور محل کا خیا ل رکھنابھی ضروری ہوتا ہے اگر ایک حلال کام کے کر نے سے نا پسند یدگی کے ساما ن پیدا ہو تے ہوں تو اس کا م سے بہر حال اجتناب کیا جائےگا.مثلاً پیاز کھانا حلا ل ہے لیکن مسجد میں پیاز کھا کر جانا منع ہے(بخاری کتاب الأطعمۃ باب ما جاء فی کراھیۃ أکل الثوم والبصل ) کیونکہ وہاں لوگوں کو اس کی بو سے تکلیف ہوتی ہے.اسی طرح انسا ن کے لئے یہ حلال ہے کہ وہ سبز رنگ کا کپڑا پہنے یا اُودے رنگ کا کپڑا پہنے یا زرد رنگ کا کپڑا پہنے.لیکن اگر کسی کا دوست کہے کہ یہ زرد رنگ کا کپڑا خرید لو.تو وہ کہتا ہے مجھے زرد رنگ اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کے نزدیک حلال وہ چیز ہے جو اس کی پسند کے مطابق ہو اور اس کی طبیعت کو اچھی لگتی ہو.کھا نے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال اور طیّب چیزیں کھاؤ.لیکن بعض لوگ بینگن نہیں کھا تے بعض لو گ کدو کوپسند نہیں کر تے.اگر ان سے پو چھا جا ئے کہ آ پ بینگن کیو ں نہیں کھا تے تو وہ کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں یا دوسرے شخص سے پو چھا جا ئے کہ آ پ کدو کیوں نہیں کھا تے تو وہ کہتا ہے کہ میر ی بیوی اس کو نا پسند کرتی ہے.اسی طرح جو لو گ مکا ن تیا ر کر تے ہیں وہ اپنے مذاق اور طبیعت کے مطا بق مکا ن بنا تے ہیں.کوئی ایک منزلہ مکا ن بناتا ہے.کو ئی دو منزلہ اور کو ئی سہ منز لہ.کو ئی مکا ن میں با غیچہ لگا نا پسند کر تا ہے اور کو ئی بغیر با غیچہ کے رہنے دیتا ہے.اب یہ سا ری چیزیں حلال ہو تی ہیں لیکن وہ سب پر عمل نہیں کر تا.جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہر حلال با ت پر عمل کر نا ضروری نہیں.لیکن جب بیوی کو طلاق دینے کا معا ملہ پیش آ جا ئے تو یہ کہتے ہو ئے کہ بیوی کو طلاق دینا جا ئز ہے فوراً بے سوچے سمجھے اسے طلا ق دے دی جا تی ہے.حا لا نکہ بعض حلال چیزیں انسا ن اپنے نفس کی خا طر بعض اپنے دوستوں کی خا طر اور بعض سو سا ئٹی کی خا طر ہمیشہ چھو ڑتا رہتا ہے درحقیقت ایسے مو قعہ پر ایک مو من کی حا لت یہ ہو تی ہے کہ وہ اس حلال کو خدا تعالیٰ کی خا طر چھو ڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ چو نکہ یہ کا م میرے
Page 364
خدا کو پسند نہیں اس لئے میں یہ کا م نہیں کر تا تا میرا خدا مجھ پر نا راض نہ ہو.پس رُ شد و ہدا یت یہ نہیں کہ طلاق کو عا م کیا جا ئے بلکہ رشد و ہدا یت یہ ہے کہ طلاق سے بچنے کی کوشش کی جا ئے.حلال کے معنے یہ ہیں کہ چا ہو تو کرسکتے ہو.یہ قانو ن کے لحا ظ سے منع نہیںلیکن تمہیں دوسروں کے خیا لات.دوسروں کے جذبات.دوسروں کی ہمدردی اور دوسروں کے پیارکو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے جس حلال پر عمل کرنے سے دوسروںکے خیالات.دوسروںکے جذبات.دوسروںکی ہمدردی اور دوسروں کے پیار کاخو ن ہوتا ہو.وہ حلال نہیں بلکہ ایسا حلال ایک جہت سے حلال ہے اور دوسری جہت سے حرام ہے.جب لوگ اپنے دوستوں کی نا راضگی اور قوم کی نا را ضگی کا خیال رکھتے ہیں تو کیا خدا تعا لیٰ کی نا را ضگی ہی ایسی چیز ہے جس سے انسا ن کو بے پرواہ ہو جانا چا ہیے؟ کیا خدا تعا لیٰ کا وجود ہی ایسا کمزور ہے کہ جس کی نا راضگی انسا ن کے لئے قا بل اعتناء نہیں؟ جب دنیوی اور سفلی عشق رکھنے والے لوگ اپنے محبوب کی چھو ٹی سے چھو ٹی خفگی سے بھی ڈرتے ہیں اور اس کو نا راض ہو نے کا موقعہ نہیں دیتے.تو ایک مومن رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہٖ ووسلم کی یہ حد یث پڑھ کر یا سن کر کہ اِنَّ اَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَاللّٰہِ الطَّلَاقُ کس طرح آ سا نی سے یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی کر ے.جب شریعت کہتی ہے کہ تم اس اَبْغَضُ الْحَلَال کو اختیار کرنے سے پر ہیز کرو تو ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ ایسے امور میںکمی پیدا کرنے کی کو شش کرے.اور اس با ت کو میا ں بیوی کے تعلقات کی کشیدگی کے وقت بھول نہ جا ئے.یہ با ت بھی یا د رکھنی چا ہیے کہ طلاق اور خلع درحقیقت ایک ہی معنے رکھتے ہیں.اگر مرد عورت کو چھو ڑتا ہے تو وہ طلاق ہو جائےگی اور اگر عورت میاں سے یہ مطا لبہ کرے کہ وہ اسے آ زاد کر دے تو وہ خلع کہلائےگا اور خلع بھی اَبْغَضُ الْحَلَال کے ما تحت ہی آئےگا.جہا ں تک نسوا نی حقوق کا سوا ل ہے خلع کا مسئلہ مسلما ن بالکل بھو ل چکے تھے جس کی وجہ سے عورتوں کے لئے ازحد مشکلات کا سا منا تھا.احمدیت نے ان کے اس حق کو قائم کیا اور عورتوں کو ان تکا لیف سے نجا ت دی جو ان حقوق کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کو پہنچتی تھیں لیکن سا تھ ہی اس حدیث کے مضمون کو بھی لو گو ں کے سامنے بو ضاحت بیا ن کیا کہ ان دونوں رستوں کو اختیار کر نااللہ تعالیٰ کے نزدیک اَبْغَضُ الْحَلَال ہے.قر آ ن کریم کا حکم ہے کہ جب میا ں بیوی میں کو ئی جھگڑا پیدا ہو جا ئے تو اس کو دُور کر نے کے لئے حکم مقرر کئے جا ئیں.جو کوشش کر یںکہ ان کی رنجش دور ہو جا ئے اور وہ پہلے کی طرح پیار اور محبت کی زندگی بسر کرنے لگیں.لیکن اگر ایسے ہی حا لات پیدا ہو جا ئیں کہ صلح کی کو ئی صورت نہ ہو سکے تو پھر خلع کی صورت میں قا ضی کے سپرد یہ معا ملہ کیا جا ئے اور وہ اس کا فیصلہ کر ے.بہر حال یہ امر اچھی طرح یا د کھنا چا ہیے کہ ذرا ذرا سی بات پر خلع اور
Page 365
طلاق تک نوبت پہنچا دینا نہایت افسوس ناک امر ہے اور یہ اتنا بھیانک اور نا پسندیدہ طر یق ہے کہ ہر شریف آ دمی کو اس سے نفرت ہو نی چا ہیے.فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا پھر اگر( اوپر کی بیان کردہ دو طلاقوں کے گزر جانے کے بعد بھی خاوند اسے تیسری) طلاق دے دے تو وہ عورت اس غَيْرَهٗ١ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ اَنْ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنْ کے لئے جائز نہ ہوگی جب تک کہ وہ اس کے سوا( کسی) دوسرے خاوند کے پاس نہ جائے.لیکن اگر وہ( بھی) اسے ظَنَّاۤ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ١ؕ وَ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا طلا ق دےدے تو ان دونوں کو بشرطیکہ انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کی( مقرر کردہ) حدّوں کو قائم رکھ سکیں گے آپس میں لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ۰۰۲۳۱ دوبارہ رجوع کر لینے پر کوئی گناہ نہ ہوگا.اور یہ اللہ کی( مقرر کردہ) حدّیں ہیں جنہیں وہ علم والے لوگوں کے لئے کھول کر بیان کرتا ہے.تفسیر.پہلے فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍمیں دو صورتیں بیا ن کی تھیں.اب طلاق وا لی صورت کو علیٰحدہ بیان کر تا ہے.اور فر ما تا ہے کہ اگر تیسری طلاق بھی وا قع ہو جائے تو اس صورت میں وہ عورت اس مرد کے لئے جا ئز نہیں ہو گی ہا ں اگر وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر دوسرا بھی اسے طلاق دےدے یا فوت ہو جا ئے اور پھر وہ پہلا شخص اور یہ عورت یقین رکھتے ہوں کہ وہ حدود اللہ کو قا ئم رکھ سکیں گے تو پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے.حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاسے روا یت ہے کہ طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأتَہٗ ثَلَا ثًا.فَتَزَ وَّجَھَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَھَا قَبْلَ اَنْ یَّدْ خُلَ بِھَا فَاَ رَادَ زَوْجُھَا الْاَ وَّلُ اَنْ یَّتَزَوَّجَھَا فَسُئِلَ رُسوْلُ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ و سلم عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا حَتّٰی یَزُوْقَ الْاٰخِرُمِنْ عُسَیْلَتِھَا مَا ذَاقَ اْلاَوَّلُ(مسلم کتاب النکاح باب لا تحل المطلقۃ ثلاثا...) یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اور پھر اس کی بیوی نے ایک اور
Page 366
شخص سے نکاح کر لیا مگر اس نے بھی شا دی سے قبل اسے طلاق دے دی.اس پر اس کے پہلے خاوند نے چا ہا کہ وہ دوبارہ اس عورت سے نکا ح کر لے اور اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوا ل کیا گیا کہ کیا وہ اس عورت سے نکا ح کر سکتا ہے؟ آ پ نے فر ما یا نہیں.جب تک دوسرا خا وند اس سے صحبت نہ کر ے اور پھر کسی وجہ سے اسے طلا ق نہ دےدے وہ پہلے کےلئے جا ئز نہیں ہو سکتی.غرض دوسرے خا وند کا ہم صحبت ہونا شرط ہے اس کے بغیر وہ پہلے خاوند کے عقد میں نہیں آ سکتی.مسلمانو ں نے اپنے تنزل کے دور میں جہا ں اور بہت سی خلافِ اسلام رسوم اپنے اندر دا خل کر لیں تھیں وہا ں انہوں نے حلالہ جیسی گندی رسم بھی اپنے اندر جا ری کرلی.یعنی انہوں نے طلاق بتّہ کے بعد عورت کو اپنے پہلے خا وند کے نکا ح میں لانے کا یہ نرا لا ڈھنگ نکا لا کہ مطلّقہ عورت سے کسی غیر شخص کا صرف ایک رات کےلئے نکاح کر دیا جاتا اور وہ اس سے ہم صحبت ہو تا اور صبح اٹھ کر وہ اس عورت کو طلاق دےدیتا تا کہ وہ اپنے پہلے خا وند سے دوبارہ نکا ح کر سکے.گو یا اس نکاح کا ڈھونگ صرف اس لئے رچایا جا تا کہ پہلے خا وند سے اس کا نکا ح کیا جا سکے.مگر اسلا م اس طریق کو نا جائز قرار دیتا ہے اور حلالہ کرنے اور کر وانے وا لوں پر لعنت ڈالتا ہے.چنا نچہ احا دیث میں آ تا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا لَعَنَ اللّٰہُ الْمُحَلِّلَ وَا لْمُحَلَّلَ لَہٗ (سنن ترمذی کتاب النکاح باب فی المحلل والمحلل لہ) یعنی اللہ تعالیٰ حلا لہ کرنےوا لے پر بھی اور جس کےلئے حلا لہ کیا گیا ہو اس پر بھی لعنت ڈا لتا ہے پس حلا لہ کی اسلا م میں کوئی جگہ نہیں اسلامی قا نون یہی ہے کہ تین طلا ق کے بعد عورت کسی اور مرد سےبا قاعدہ شا دی کر ے اور اپنی زندگی اس کے گھر میں گزارے پھر اگر کسی وجہ سے وہ بھی طلا ق دےدے یا وفات پا جا ئے تو عورت اپنے پہلے خا وند سے نئے مہر اور ولی کی رضا مندی سے دوبارہ نکا ح کرسکتی ہے.اس کے بغیر نہیں.وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مقررہ مدت (کی آخری حد) کو پہنچ جائیں تو یا تو انہیں مناسب طور پر روک لو بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ١۪ وَّ لَا تُمْسِكُوْهُنَّ یا انہیں منا سب طور پر رخصت کردو.اور انہیں تکلیف دینے کے لئے (اس نیت سے) کہ( بعد میں پھر )ان پر ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا١ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ١ؕ زیادتی کرو مت روکو.اور جو شخص ایسا کرے تو (سمجھو کہ )اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا ہے.اور تم اللہ (تعالیٰ) کے
Page 367
وَ لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا١ٞ وَّ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ احکام کو محل تمسخر نہ بناؤ.اور تم پر جو اللہ کا انعام ہوا ہے (اس کو )یاد رکھو.اور( اسے بھی یاد رکھو )جو اس نے اتاراہے وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ١ؕ وَ یعنی کتاب اور حکمت (کو )کہ وہ اس کے ذریعہ سے تمہیں نصیحت کرتا ہے.اور اللہ کا تقویٰ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌؒ۰۰۲۳۲ اختیار کرو اور جان لو کہاللہ ہر ایک بات کو خوب جانتاہے.حلّ لُغات.ھُزُ وًا مصدر ہے اور اس کے معنے ہنسی کر نے کے ہیں.اس آیت میں یا تو مصدر بمعنے مفعول ہے یعنی جس سے ہنسی کی جا ئے.یا مصدر مبا لغہ کےلئے ہے کیو نکہ بعض اوقات مصدر مبا لغہ کے معنوں میں بھی استعما ل ہو تا ہے.یا حذف مضا ف ہے.یعنی ہنسی کا مقام (اعراب القرآن الکریم للدرویش).تفسیر.اس آ یت میں طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ سے مراد طلاق رجعی ہے اور بَلَغْنَ اَجَلَھُنَّ کے دو معنے ہیں.اوّل میعاد کے ختم ہو نے کے قریب پہنچ جا نا (۲) مدت کا ختم ہو جا نا(لسان العرب).اس جگہ پہلے معنے مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ جب دوسری طلا ق کے بعد عدت ختم ہو نے لگے تو تمہیں رجوع کا اختیار ہے.فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ میں دوبا رہ اس مسئلہ پر زور دیا کہ عورتوں سے دو ہی قسم کے سلوک کر نےکا حکم ہے.یا تو انہیں مناسب رنگ میں اپنے پا س رکھ لو.یا منا سب رنگ میں رخصت کر دو.یہ نہ ہو کہ تم اس نیت کے ساتھ رجو ع کر و کہ بعد میں پھر اسے دکھ دینے کا ایک موقعہ تمہا رے ہا تھ آ جائےگا.وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ اور جو شخص عورت کو دکھ دینے کےلئے ایسا کرےگا وہ بظاہر تو اپنی بیوی کو دکھ دے رہا ہو گا لیکن درحقیقت اپنی جا ن پر ظلم کر رہا ہو گا.اس لحا ظ سے بھی کہ اس سے تمدن میں ابتری پیدا ہو گی اور اس لحاظ سے بھی کہ وہ عورت پر ظلم کرکے اپنی شقا وت قلبی کا ثبوت لو گو ں کے لئے مہیّا کرے گا.وَ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ مَاۤ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَ الْحِكْمَةِ.فر ما یا دوسری قوموں کو تو یہ تعلیم نصیب ہی نہیں ہو ئی.تمہیں یہ پا ک تعلیم دی گئی ہے جس کی با ت بات حکمت پرمبنی ہے.تمہا را فرض ہے کہ تم اس پر عمل کر و اوراللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے دوسری قوموں کی طرح تمہیں ٹھوکریں کھا نے سے بچا لیا ہے.اگر تم نے اس
Page 368
بابرکت تعلیم سے فا ئدہ نہ اٹھا یا اور تم بھی اپنی نفسا نی خو اہشا ت کے پیچھے پڑ گئے تو تم سے زیا دہ بد قسمت اور کو ن ہو گا؟ تمہیں چا ہیے کہ تم ان احکا م اور ہدا یات پر عمل کر و اور وہ طریق اختیار نہ کرو جو تقویٰ کے خلا ف ہو.وَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اور جب تم عورتوں کو طلاق دواور وہ اپنی عدت کو پورا کرلیں.تو تم انہیں جب کہ وہ نیک طریق پر باہم رضامند ہو جائیں اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ١ؕ اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کر لینے سے مت روکو.یہ (وہ بات) ہے کہ جس کی تم میں سے ہر اس شخص کو جو اللہ پر ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ١ؕ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے.(اور سمجھ لو کہ )یہ بات تمہارے حق میں سب سے زیادہ برکت ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ١ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۰۰۲۳۳ والی اور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے.اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.حل لغات.تَعْضُلُوْھُنّ.عَضَلَ عَلَیْہِ عَضْلًا کے معنے ہیں.ضَیَّقَ عَلَیْہِ وَحَبَسَہٗ وَمَنَعَہٗ.(اقرب) یعنی کسی پر نا وا جب تنگی ڈالنا.اس کو روکے رکھنا اور اسے دوسرے کا موں سے منع کر دینا.ان معنوں کے لحا ظ سے لَاتَعْضُلُوْهُنَّ کا تر جمہ یہ ہو گا.کہ ان کوتنگ مت کر و.یا بند نہ کر و.یا روکو نہیں.اَ زْکٰی کے معنے اَنْفَعُ کے بھی ہیں اور (۲) زیادہ پا کیزہ کے بھی ہیں.تفسیر.اس آ یت میں بَلَغْنَ کے وہ معنے نہیں جو پہلے بیا ن ہو ئے ہیں بلکہ اس جگہ میعا د کے ختم ہو نے کے معنے ہیں.اور اَجَل سے حر یت وا لی مدت مرا د ہے کہ جب وہ عدت پوری کر لیں اور آ زادی کے زما نہ میں آ جا ئیں فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ میں ازوا ج کے متعلق اختلا ف ہوا ہے.(۱) بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلا خا وند مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس سے صلح کر لے.اس مفہوم کو مدّ نظر رکھتے ہو ئے طَلَّقْتُمْ سے مراد طلاق رجعی ہو گی تین طلا قیں مراد نہ ہوںگی.(۲) بعض کہتے ہیں کہ خاوند سے مرا د آئندہ ہو نے والا خا وند ہے، اس صورت میں
Page 369
اور اس میں جس قدر حکمتیں ہیں کوئی کتاب ان کی مثال پیش نہیں کر سکتی.مگر یہ ضروری نہیں کہ ساری حکمتیں ہر شخص پر کھل جائیں.ہاں ہر زمانہ میں قرآن کریم کے کچھ نئے معنے کھلتے ہیں اور اُن کے علاوہ کچھ زائد معنے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اگلوں کے لئے رکھے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی.جو لوگ قرآن کریم میں نسخ قرار دیتے ہیں.وہ اس کے ثبوت کے طور پر اس قسم کی کوئی دلیل پیش نہیں کرتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فلاں آیت منسوخ ہے.یا آپؐ نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت منسوخ کر دی ہے یا لوگ آپؐ کی مجلس میں آئے ہوں اور آپؐ نے فرمایا ہو کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ آج رات یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے.وہ صرف استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ فلاں آیت کا فلاں آیت کے مخالف مفہوم ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ناسخ ہے اور دوسری منسوخ.گویا جو آیت بھی اُن سے حل نہیں ہوتی اُسے وہ منسوخ قرار دے دیتے ہیں.اور یہ محض عدم علم کی وجہ سے ہوتا ہے.مگر تعجب کی بات ہے کہ اِدھر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ احاد احادیث قرآن کریم کو منسوخ نہیں کرتیں.اور یہ بات صحیح ہے.ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک چھوڑ کروڑ احاد احادیث بھی قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ نہیں کر سکتیں مگر دوسری طرف وہ اپنے ظن اور قیاس سے کام لے کر قرآن کریم کی آیات کو منسوخ قرار دینے لگ جاتے ہیں.اِنَّالِلہِ وَاِنَّااِلَیْہِ رَاجِعُوْن.منسوخ کی وہ قسم کہ جس کے الفاظ بھی منسوخ ہوں اور حکم بھی منسوخ ہو اس کی وہ کوئی مثال پیش نہیں کرتے حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی کوئی مثال پیش کرتے اور بتاتے کہ فلاں آیت قرآن کریم میں تھی اور اس کے الفاظ اور حکم دونوں منسوخ ہیں.وہ صرف تحویلِ قبلہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا حکم قرآن کریم میں تھا مگر اس کے الفاظ وہ پیش نہیں کرتے اس لئے ان کا یہ دعویٰ قابلِ اعتبار نہیں سمجھا جاسکتا.پھر جن آیات کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہؓ کو بھول گئی تھیں.اُن کا بُھولنا تو ایک معجزہ بن جاتا ہے.اگر کبھی ایسا ہوا ہوتا تو اس کے متعلق سارے صحابہؓ میں شور پڑجانا چاہیے تھا.کیونکہ آپ سینکڑوں آدمیوں کو قرآن کریم سکھاتے اور حفظ کرواتے تھے.چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک لڑائی میں ستر قاری شہید ہو گئے تھے(بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الرجیع.....).جب صرف ایک لڑائی میں شہید ہونے والوں کی تعداد اس قدر ہو تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں کس قدر قاری پائے جاتے تھے اور یہ سینکڑوں حفّاظ ان پانچ حفّاظ کے علاوہ تھے.جنہیں آیات نازل ہونے کے فوراً بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم یاد کروا دیتے تھے(بخاری کتاب العلم).یہ پانچ خاص حفّاظ تھے.اور آگے ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جن کو آیاتِ قرآنیہ حفظ
Page 370
صورت میں بھی رضا مند نہ ہوں تو وہ حاکم وقت اور قا ضی کے ذریعہ کسی دوسری جگہ جہا ں وہ اجازت دے نکا ح کراسکتی ہے یا قا ضی کی معرفت اولیاء پر دباؤ ڈال سکتی ہے کہ وہ روکیں نہ ڈالیں.ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَ اَطْهَرُ میں بتا یا کہ یہ قا نو ن تمہا رے لئے دینی اور دنیوی دونوں لحاظ سے بڑا مفید اور با بر کت ہے.یعنی تمدنی نقطہ نگا ہ سے بھی اس قانو ن کی متا بعت تمہا رے لئے مفید ہے اور اخلاقی نقطہء نگاہ سے بھی یہ قانون تمہارے اندر پا کیزگی کی روح پیدا کر نے والا ہے.وَ الْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں.(یہ ہدایت )ان اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ١ؕ وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ کے لئے (ہے) جو دودھ پلانے (کے کام) کو (اس کی مقررہ مدت تک) پورا کرنا چاہیں.اور جس کا بچہ ہے اس کے كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ١ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا١ۚ لَا ذمہ حسب دستور ان( دودھ پلانے والیوں )کا کھانا اور ان کی پوشاک ہے.کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ١ۗ وَ عَلَى ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی.کسی والدہ کو اپنے بچے کے ذریعہ سے دکھ نہ دیا جائے.اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ١ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ سے(دکھ دیا جائے)اور وارث پر (بھی )ایسا ہی (کرنا لازم )ہے.اور اگر وہ دونوں آپس کی رضا مندی اور مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا١ؕ وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ باہمی مشورہ کے ساتھ دودھ چھڑانا چاہیں تو (اس میں )ان پر کوئی گناہ نہیں.اور اگر تم اپنے بچوں کو (کسی دوسری
Page 371
تَسْتَرْضِعُوْۤا۠ اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ عورت سے)دودھ پلوا نا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم وہ (معاوضہ )جوتم نے دینا کیا ہے اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ١ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا مناسب طور پر ادا کردو.اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۰۰۲۳۴ اللہ اسے یقیناً دیکھتا ہے.حل لغا ت.تَسْتَرْ ضِعُوْا اِسْتَرْ ضَعَ کے معنے ہیں طلب مُرْ ضِعَۃً اُس نے کسی دودھ پلا نے والی عورت کو طلب کیا.اور اِسْتَرْ ضَعَ وَالِدُہٗ کے معنے ہیں وا لد نے اپنے بچہ کو کسی اور سے دودھ پلوا لیا.اور اِسْتَرْ ضَعَتِ الْمَرْأَۃُ الطِّفْلَ کے معنے ہیں اِتَّخَذَتْ مُرْ ضِعَۃً لَھَا.اس نے دودھ پلا نے کےلئے دایہ کو رکھ لیا.(تاج العروس) تفسیر.چو نکہحَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ سے یہ دھو کا لگ سکتا تھا کہ دو سال تک رضاعت ضروری ہے اس لئے لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ فر ما کر بتا دیا کہ اس سے کم مدّت بھی ہو سکتی ہے.لیکن اس میں دو سا ل سے زیا دہ کی نفی بھی کر دی گئی ہے کیو نکہ کَامِلِیْنَ کا لفظ بتا تا ہے کہ دو سال سے زیا دہ دودھ پلا نا جا ئز نہیں.وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ میں کھا نے اور کپڑے سے مرا د تما م اخرا جا ت ہیں نہ کہ صرف روٹی اور لباس.اور معروف سے مراد با پ کی مقدرت ہے کہ امیر اپنی طا قت کے مطا بق دے اور غریب اپنی طا قت کے مطا بق.اس جگہ عا م دودھ پلا نے وا لی عورتوں کا ذکر نہیں بلکہ ماؤں کا ذکر ہے.اور یہ ذکر طلاق کے ضمن میں کیا گیا ہےکہ اگر دودھ پلانے والی عورت کو طلا ق دی جا ئے تو بچہ کی خا طر عورت کے لئے یہ ضروری ہے کہ بچے کو دودھ مقررہ مدت تک پلا ئے اور اس کے بدلہ میں خا وند پر فرض ہے کہ عا م مزدور عورت کی طرح نہیں بلکہ اپنی تو فیق کے مطا بق اسے خرچ دے کیو نکہ یہ امر عورت کے جذبا ت کو ٹھیس پہنچانے والا ہو گا کہ ایک طرف تو اسے مجبور کیا جائے کہ وہ طلا ق کے بعد بھی بچہ کو دودھ پلا تی رہے.اور دوسری طرف اسے ایسی حا لت میں رکھا جا ئے جو پہلی حالت سے ادنیٰ ہو اور اس کے لئے ذلت کا مو جب ہو مگر اس کے سا تھ ہی لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا کہہ کر اس
Page 372
طرف اشا رہ فر مادیا کہ مر د سے یہ مطا لبہ کر نا کہ وہ اپنی طا قت سے زیا دہ خرچ کر ے یہ بھی نا منا سب ہے اور عورت سے یہ مطا لبہ کر نا کہ وہ ایک نوکر کی طرح طلا ق کے بعد ایک عرصہ گھر میں گزار دے یہ بھی نا منا سب ہے.لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ ما ں اپنے بچہ کی وجہ سے با پ کو ضرر نہ دے اور یہ بھی کہ ما ں اپنے بچے کی وجہ سے ضرر نہ دی جا ئے اس آ یت میں مر د اور عورت دونو ںکو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ بچہ کو ایک دوسرے پر دباؤ ڈا لنے کا ذریعہ نہ بنا ؤ.بہت سے نا دا ن اس حرکت کے مر تکب ہو تے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ یا تو بچے ہلا ک ہو جا تے ہیں یا ان کی تر بیت خراب ہو تی ہے.اس قسم کا فعل درحقیت قتلِ اولاد کے مشا بہ ہے.اور قرآ ن کر یم نے اس سے روک کر آ ئندہ اولا دوں پر احسان عظیم کیا ہے.وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ کا عطف وَ عَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ پر ہے.اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حق قا ئم کیا ہے جو تمدن کی صورت ہی بدل دیتا ہے.اور حکم دیا ہے کہ اگر با پ مر جا ئے تو باپ کے جو ورثاء ہو ں.ان پر بچہ کو دودھ پلا نے وا لی عورت کا خرچ ہو گا.گو یا ورثہ کے سا تھ بو جھ بٹا نے کا کا م بھی ان کے سپرد کر دیا.خواہ انہیں ترکہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، تھوڑا ہو یا بہت.چنا نچہ فر ما یا وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ.وارث پر بھی ویسا ہی حق ہے جیسا کہ با پ پر یعنی با پ کا وارث خوا ہ لڑکا ہو خواہ کو ئی قریبی رشتہ دار اس پر یہ خرچ وا جب ہو گا.یعنی اس کی پر ورش کر نا احسا ن کے طور پر نہیں ہو گا بلکہ ایک حق کے طور پر ہو گا جواللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وا جب کیا گیا ہے.اور یہ بھی مطلب ہے کہ اس بچہ کے حصہ میں سے خر چ دیا جا سکتا ہے.بہر حال اس آ یت میںاللہ تعالیٰ نے تمدن کی ایک نئی بنیا د رکھی ہے کہ کمزور بچوں کی تربیت بطورحق ورثاء پر ڈال دی ہے.یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب دودھ پلا یا جا چکے تو پھر وہ بچوںکو لا وارث چھو ڑ دیں بلکہ اس حق کو بلو غث تک ممتد کر نا پڑے گا اور ان کا فرض ہو گا کہ وہ بچہ کے کھا نے اور لبا س کے اخراجا ت کے علا وہ اس کے تعلیمی اخرا جات بھی با لغ ہو نے تک پورے کر یں اور اس کی اعلیٰ درجہ کی تر بیت مد نظر رکھیں تا کہ وہ قوم کا ایک مفید وجود بن سکے.بعض لو گ کہتے ہیں کہ یہ خرچ نسبتی طور پر تمام ورثاء پر پڑے گا.اور بعض کہتے ہیں کہ صرف سب سے بڑھ کر حق وراثت رکھنے والا شخص اس کا ذمہ دار ہو گا.خواہ اسے ترکہ میں سے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو.فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا سے معلوم ہو تا ہے کہ بچے کے متعلق دودھ پلانے یا چھڑانے کا فیصلہ قر آ ن کر یم نے نہ مر د کے اختیا ر میں رکھا ہے نہ عورت کے اختیار میں بلکہ دونوں کومشترکہ اختیار دیا ہے.شا ید تما م شرا ئع کی تاریخ میں یہ منفرد مثا ل ہے کہ اس طرح اہلی معا ملا ت میںمیا ں بیوی کو ایک مقا م
Page 373
پر کھڑا کر کے برا بر کے اختیار دیئے گئے ہیں.ہا ں یہ شرط ضرور ہے کہ دودھ پلا نے کی جو مدت قرآن کر یم نے مقرر کی ہے اس سے زیا دہ دیر تک دودھ پلا نے پر نہ خا وند مجبور کر سکتا ہے نہ عورت زور دے سکتی ہے.جب طلا ق کے بعد بھی عورت کے جذبات کا اس قدر خیال رکھنے پر خا وند کو مجبو ر کیا گیا ہے تو ظا ہر ہے کہ جو عورت نکا ح میں ہو ان امور میں اس کے جذبات کا خیال رکھنا اسلام کے نزدیک کس قدر ضروری ہو گا.وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْۤا۠ اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّاۤ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ میں بتا یا کہ بچوں کو دوسروں سے دودھ پلوا نا حقوق پدری کے خلا ف نہیں نہ حقوق ما دری کے خلا ف کہ اس کو گنا ہ سمجھو گنا ہ تب ہو گا اگر بلا اجرت دینے کے ظلماً کسی سے یہ کا م لو.کیو نکہ اس صورت میں تم نے دو گنا ہ کئے ایک تو دوسرے کا ما ل لینے کا اور ایک بچہ کے حقوق ادا نہ کر نے کا.انہی معنوں سے لَا جُنَا حَ کے معنے حل ہو تے ہیں.اس سے معلوم ہو تا ہے کہ بچے کے حقوق بطور حق کے ہیں اور ان میں کمی کر نا مو جب گنا ہ ہو تا ہے.اِذَا سَلَّمْتُمْ مَآاٰتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ کے متعلق سوا ل پیدا ہو تا ہے کہ یہ تو بظاہر ایک بے معنی فقرہ معلو م ہو تا ہے.کیو نکہ اس کے لفظی معنے یہ بنتے ہیں کہ جب تم دے دو جوتم دے چکے ہو.حالا نکہ جو معا وضہ ایک دفعہ دے دیا گیا ہو اس کے دوبا رہ دینے کا سوا ل ہی پیدا نہیں ہوتا.اس مشکل کو دیکھتے ہو ئے بعض لو گ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو تا ہے کہ مر ضعہ کی مزدوری پہلے دینی ضروری ہے مگر میرے نزدیک اس سے مزدوری پہلے دینا ثا بت نہیں کیونکہ سَلَّمَ کے معنے صرف سپر د کرنے کے ہی نہیں ہو تے بلکہ اس کے معنے را ضی ہو نے کے بھی ہو تے ہیں.چنا نچہ عربی زبا ن میں سَلَّمَ بِہ کے معنے ہو تے ہیں رَضِیَ وہ اس سے را ضی ہوگیا.(اقرب) قر آ ن کر یم میںبھی یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا(النسا ء : ۶۶) یعنی تیرے ربّ کی قسم جب تک وہ ہر اس با ت میںجس کے متعلق ان میں جھگڑا ہو جا ئے وہ تجھے حکم نہ بنا ئیں اور پھر جو فیصلہ تو کر ے اس سے وہ اپنے نفوس میںکسی قسم کی تنگی محسوس نہ کر یں اور پورے طور پر را ضی نہ ہو جا ئیں اس وقت تک وہ ہر گز مو من نہیں ہو ںگے، ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہو ئے اِذَا سَلَّمْتُمْ کے یہ معنے ہوںگے کہ جب تم دودھ پلا نے وا لیوں کو منا سب حق دینے پر رضا مند ہو جا ؤ اور تمہا ری نیت یہ ہو کہ تم اتنی رقم بہر حا ل دے دو گے تو پھرکسی دوسری عورت سے دودھ پلوا نے میں کو ئی حرج نہیں.گو یا ایتان بالمعروف پر با ہم رضا مند ہو جا نے کے بعد اگر کسی اور سے دودھ پلوا لو تو کو ئی گنا ہ نہ ہو گا.ان معنوں کے لحا ظ سے اُجرت کا پہلے دینا ضروری نہیں.مگر اجر ت کا پہلے مقرر ہو جانا بہر حال ضروری ہے.لیکن اگر سَلَّمْتُمْ کے
Page 374
معنے سپر د کر نے کے بھی لئے جا ئیں تب بھی اس کے یہ معنے نہیں ہیں کہ پہلے اجر ت سپرد کرو تب دودھ پلوا نا جا ئز ہو گا بلکہ یہاں ایک قا عدہ بیا ن ہوا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اجرت سپر د نہ کرو گے تو گنا ہ ہو گا گو یا اِذَاسَلَّمْتُمْ فَلَا جُنَا حَ عَلَیْکُمْ کے سا تھ ہے نہ کہ تَسْتَزْضِعُوْا کے سا تھ.مگر سَلَّمْتُمْ کے معنے حل کر نے کے بعد بھی یہ سوا ل قا ئم رہتا ہے کہ اس جگہ اٰتَیْتُمْ کا لفظ استعما ل کیا گیا ہے جس کے لفظی معنے ہیں ’’تم نے دے دیا ہے‘‘ یا ’’ تم دے چکے ہو‘‘.اس لحا ظ سے اس کے معنے یہ بنتے ہیں کہ جب تم اس حق پر رضا مند ہو جا ؤ جو تم دے چکے ہو.اور ظا ہر ہے کہ یہ ایک بے معنے فقرہ بن جا تا ہے.سویاد رکھنا چا ہیے کہ عر بی زبان میں کبھی ما ضی کا صیغہ قطعی فیصلہ پر دلا لت کر نے کے لئے بھی استعمال کیا جا تا ہے.جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ ( المائدۃ:۷).جب تم نما ز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے مو نہوں کو اور اپنے ہا تھو ں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو حا لا نکہ وُضو نماز کے لئے کھڑے ہو نے سے پہلے کیا جاتا ہے نہ کہ کھڑے ہو تے وقت.پس یہاں یہی مراد ہے کہ جب تم نما ز کا پختہ ارادہ کر لو تو پہلے وُ ضو کر لیا کر و.اور یہی اٰتَیْتُمْ کے معنے ہیں کہ جو کچھ تم اسے دینے کا پختہ فیصلہ کر چکے ہو.اگر اس کے یہ معنے نہ کئے جا ئیں تو آ یت کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ پہلا روپیہ جو تم اسے دے چکے ہو وہ اسے پھر دے دو.یعنی اگر پہلے سو روپیہ دے چکے تھے تو پھر اور سو روپیہ دےدو حا لانکہ اسے کوئی بھی تسلیم نہیں کر تا.درحقیقت اس کے یہی معنے ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں کو کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا نا چا ہو تو اس میں کو ئی حرج نہیں بشر طیکہ تم نے اسے جو کچھ دینے کا پختہ فیصلہ کیا ہے اس پر پورے طور پر قا ئم ہو جا ؤ اور اس میں کسی قسم کی حیل و حجت سے کا م نہ لو.اس آ یت میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ حق الخد مت کے لئے ضروری ہو تا ہے کہ اس کے ادا کرنے کا انسا ن ایسا عہد کر ے کہ گو یا ادا کرہی دیا ہے اور با لمعروف کہہ کر اس امر کی طرف تو جہ دلا ئی ہے کہ حق الخدمت ادا کر نے میں معروف کو مد نظر رکھنا ضروری ہو تا ہے.یعنی معا وضہ ملک کی اقتصا دی حا لت کے مطا بق ادا کیا جا ئے.اس قدر کم نہ ہو کہ اس وقت کی اقتصا دی حا لت کے مطا بق اس سے دودھ پلا نے وا لی عورت کا گزارہ ہی نہ ہو سکے.اسی طرح با لمعروف میں اس امر کی طر ف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہا ری مالی حالت عا م لو گو ں سے اچھی ہو تونہ صرف پہلی حد بندی کو مدّ نظر رکھو بلکہ اس سے زائد یہ امر بھی مدنظررکھو کہ ایسا حق الخدمت ادا کرو.جو تمہاری اپنی ما لی حالت کے مطا بق ہو.گویا کم سے کم حق الخدمت تو وہ ہو جو اس زمانہ کے حالات کے مطابق گزارہ کے لئے کا فی ہو.لیکن اگر ہو سکے تو اس سے زیا دہ دو اور صرف زما نہ کے حا لا ت کے مطا بق ہی نہ دو بلکہ اپنی ما لی حا لت کو مد نظر رکھتے ہو ئے ایسا معاوضہ دو جو تمہا رے حا لات کے مطا بق ہو.
Page 375
وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ اور تم میں سے جن( لوگوں) کی روح قبض کر لی جاتی ہے.اور وہ (اپنے پیچھے) بیویاں چھوڑ جاتے ہیں (چاہیے کہ) بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا١ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ وہ (یعنی بیویاں) اپنے آپ کو چار مہینے (اور) دس (دن) تک روک رکھیں.پھر جب وہ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ اپنا مقررہ وقت پورا کر لیں وہ اپنے متعلق مناسب طور پر جو کچھ (بھی) کریں اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں.بِالْمَعْرُوْفِ١ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۰۰۲۳۵ اور جو تم کرتے ہو اللہ (تعالیٰ) اس سے واقف ہے.حلّ لُغات.یَتَرَ بَّصْنَ میں مبتدا محذوف ہے.یعنی حُکْمُ اَ زْوَاجِھِمْ اَنْ یَّتَرَ بَّصْنَ اَوْ اَ زْوَاجُھُمْ یَتَرَ بَّصْنَ یعنی حُکْمُ اَ زْوَاجِھِمْ مبتدا ہے جو محذوف ہے اور اَنْ یَّتَرَ بَّصْنَ اُس کی خبر ہے.(املاء ما منّ بہ من الرحمٰن) تفسیر.اس آ یت سے استدلال کر تے ہو ئے بعض لو گ کہتے ہیں کہ اگر چا ر ماہ دس دن کی عدّت گذرنے کے بعد عورتیں اپنے مستقبل کے متعلق کو ئی قدم اٹھائیں.تو مردوں پر تو کو ئی گناہ نہ ہو گا لیکن عورتوں پر گنا ہ ہو گا کیو نکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ (البقرة:۲۴۱) یعنی عورتوںکو اپنے گھروں سے ایک سال تک کوئی شخص نکا لنے کا مجا ز نہیں.لیکن میر ے نز دیک یہ با ت درست نہیں کہ ایسی صورت میں عورتوں پر گنا ہ ہے کیو نکہ اسی آ یت میں اس کے بعد بِالْمَعْرُوْفِ کا لفظ آ یا ہے جس سے صا ف ثابت ہے کہ اگر وہ نکا ح ثا نی کرلیں تو یہ صرف جا ئز ہی نہیں بلکہ ایک پسند یدہ اور قا بل ستا ئش فعل ہے.اگر گنا ہ ہو تا تو بِا لْمَعْرُوْف کے الفاظ استعمال نہ کئے جاتے کیو نکہ معروف کے معنے را ئج الوقت قا نو ن یا فطرتی جذبہ یا عقلِ عا مہ کے مطا بق کسی کام کے کر نے کے ہو تے ہیں.اور جو کا م قا نو ن کے مطا بق ہو یا فطر تی جذ بہ کے مطا بق ہو یا انسا نی عقل اس کا تقاضا کر تی ہو اس کا م کو کو ئی دانا شخص بُرا قرار نہیں دے سکتا.در حقیقت یہ آیت ان لوگو ں کے لئے زجر ہے جو بیوہ
Page 376
عورتوں کو نکا ح ثا نی سے روکتے ہیں فر ما تا ہے.اگر وہ نکا ح کر لیں تو کیا تم پر کو ئی گنا ہ ہے.یعنی ہرگز کو ئی گناہ نہیں.پھر تم انہیں نکاح سے کیوں رو کتے ہو؟ وہ اپنے نفوس کے متعلق جو کچھ فیصلہ کر یں اس کا وہ حق رکھتی ہیں.ہا ں !اس میں یہ اشا رہ ضرور پا یا جا تا ہے کہ اگر وہ کو ئی غیر معروف کا م کر یں اور حکام و اولیاء انہیں نہ روکیں تو یہ گنا ہ ہو گا.بیوہ کے لئے چا ر ما ہ دس دن کی مدت مقرر کر نے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر عورت حا ملہ ہو تو اس عرصہ میں جنین میں حر کت پیدا ہو جا تی ہے اور اسے حمل کا یقینی طور پر علم ہوجا تا ہے.جس کے نتیجہ میں ضروری ہو تا ہے کہ وہ نکا ح کے لئے وضع حمل تک انتظار کرے.وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ عورتوں سے نکاح کی درخوات کے متعلق جو بات تم اشارۃً (ان سے) کہو النِّسَآءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ١ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ یا اپنے دلوں میں رکھو اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں.اللہ تعالیٰ جانتا ہے سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَ لٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ۠ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا کہ تمہیں ضرور ان کا خیال آئے گا.لیکن تم ان سے خفیہ طورپر (کوئی) معاہدہ نہ کرلو.ہاں یہ( اجازت ہے) قَوْلًا مَّعْرُوْفًا١ؕ۬ وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ کہ تم ان سے کوئی مناسب بات کہہ دو.اورجب تک (عدّت کا ) حکم اپنی میعاد کو (نہ )پہنچ جائے الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ١ؕ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ (اس وقت تک ) تم نکاح کرنے کا پختہ ارادہ نہ کرلو.اور جان لو کہ تمہارے دلوں میں جو (کچھ بھی) ہے اللہ( تعالیٰ) فَاحْذَرُوْهُ١ۚ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌؒ۰۰۲۳۶ اسے جانتا ہے.پس تم اس (بات) سے ڈرو.اور جان لو کہ اللہ (تعالیٰ) بہت بخشنے والا (اور) بردبار ہے.حلّ لُغات.عَرَّ ضْتُمْ عَرَّ ضْتُ لَہٗ وَعَرَّضْتُ بِہٖ تَعْرِ یْضًا کے معنے ہیں اِذَا قُلْتَ قَوْلًا وَاَنْتَ
Page 377
تَعْنِیْہِ فَا لتَّعْرِیْضُ ضِدُّ التَّصْرِ یْحِ مِنَ الْقَوْلِ( اقرب) یعنی تعر یض ایسے کلا م کوکہتے ہیں جو تصریح کے مخا لف ہو.اور صرف اشارۃً ایسی بات کہی جائے جس کا اصل مفہوم کہنے والا ہی سمجھتا ہو.صا حب مفر دات لکھتے ہیں.اَلتَّعْرِیْضُ کَلَامٌ لَہٗ وَ جْھَانِ مِنْ صِدْ قٍ وکِذْبٍ اَوْ ظَاھِرٍ وَ بَا طِنٍ یعنی تعریض ایسے کلام کو کہتے ہیں جس کے صدق اور کذب یا ظا ہر اور با طن کے لحا ظ سے دو مفہوم سمجھے جا سکیں.تَعْز مُوْا عَزَ مَ الْاَ مْرَ وَعَلَیْہِ کے معنے ہیں عَقَدَ الضَّمِیْرَ عَلَیْہِ.کسی با ت کا پختہ ارادہ کر لیا (اقرب).تفسیر.فر ماتا ہے اس میں کو ئی حرج نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکا ح کے سلسلہ میں کو ئی بات اشارۃً کہہ دو.مثلا ً کسی بیوہ سے کہہ دیا کہ مشورہ سے کام کر نا بہتر ہو گا.آ پ کواگر کو ئی ضرورت محسوس ہو تو میں ہمدردانہ مشورہ کے لئے حا ضر ہوں.اب لفظ مشورہ عا م ہے خوا ہ وہ اپنے لئے ہو یا کسی اور کے لئے.اس طرح با ت بھی مخفی رہتی ہے اور اشا رۃً اس کا اظہار بھی ہو جا تا ہے.اسی طر ح ارادہء نکا ح کو اپنے دل میں مخفی رکھنا بھی جائز ہے.تا وقتیکہ چار ما ہ اور دس دن کی میعا د نہ گزر جائے.لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ۠ سِرًّا اِلَّاۤ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا میں عورتوں سے خفیہ معا ہدہ نکا ح کی کلّی مما نعت کر تے ہو ئے قو لِ معروف کی اجا زت دی گئی ہے مگر قول معروف سے شادی کی درخوا ست مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمدردی اور غمخواری کا اظہار کرو تاکہ اس پر یہ اثر ہو کہ یہ شخص میرا خیر خوا ہ ہے.اورمیں اس سے ضرورت پر مفید مشورہ لے سکتی ہوں ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اسے صا ف طور پر نکا ح کے لئے کہہ دیاجا ئے ایسا کہنا ہر گز جا ئز نہیں.چنا نچہ فرماتا ہے.وَ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ تم دو نو ں مل کر اس امر کا فیصلہ نہ کرلو کہ عدّت کے بعد ہم آپس میں نکا ح کر لیں گے.اس سے پہلے اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ میںتو مر دوں کو سمجھا یا کہ وہ شادی کے متعلق عورتوں کے سامنے پورا اظہا ر نہ کر یں.ہا ں !اگر وہ دل میں نیت رکھیں تو اس میں کو ئی حر ج نہیں.مگر اس جگہ عورتوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ اگر وہ مر دوں کی با ت کو سمجھ جا ئیں تو فوراً ہا ں نہ کر دیں بلکہ وہ بھی خا مو ش رہیں اور اپنے ارادہء نکا ح کا ان کے سامنے اظہا ر نہ کر یں.اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اس لئے کیا ہے کہ عا م طور پرلو گ ایسے امور میں احتیاط سے کا م نہیں لیتے اور نفسا نی جو شوں سے دب جاتے ہیں.اللہ تعا لیٰ فر ماتا ہے کہ عدت کے اندر تمہارا نکا ح کے متعلق آپس میں کو ئی فیصلہ کر لینا قطعی طور پر ناجائز ہے.اس کے بعد فر ما تا ہے وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ تمہا رے دلوں میں جو کچھ ہےاللہ تعالیٰ اسے خو ب جا نتا ہے.پس تم اس سے ڈرو.اور سمجھ لو کہ کسی اور کو پتہ ہویا نہ ہوخدا تعالیٰ کو تو پتہ ہے اس لئے تم چو کس
Page 378
رہو اور احکام الٰہی کی خلا ف ورزی کر نے کی جرأ ت نہ کر و.یا یہ کہ لَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ میں دوسرا حکم ہے اور وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ میں لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ۠ سِرًّا کے حکم کے سلسلہ میں یہ بتا یا گیا ہے کہ تم ان سے کو ئی مخفی معاہدہ نہ کر و.کیو نکہ ا للہ تعالیٰ تمہا رے دل کی باتوں تک کو جا نتا ہے.وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌکا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان احکا م کی خلا ف ورزی ہو جا ئے تو تم اللہ تعالیٰ کو غَفُوْرٌاور حَلِيْمٌ پا ؤ گے.بلکہ اس میںلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ کی حکمت بتا ئی ہے.کہ چونکہ خدا تعالیٰ پردہ پو ش ہے اور وہ انسان کی کمزوری سے واقف ہے.اس لئے اس نے صرف چا ر ما ہ دس دن کی عدّت مقرر کی ہے.زیا دہ سخت احکا م اس نے نہیں دئیے.اور حلیم کہہ کر بتا یا کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے.وہ جا نتا ہے کہ اس غرض کے لئے کس قدر انتظار کر نا ضر وری ہے.اگر اس قسم کے احکا م نہ دئیے جا تے تو تمدّن میں کئی قسم کی خرا بیا ں پیدا ہو جا تیں اور سوسائٹی کا نظام درہم بر ہم ہو جا تا.پس اس خیال سے کہ نکا ح تقویٰ کا ایک ذریعہ ہے.جلدی نہ کر و.خداتعا لیٰ اس امر کو بہتر سمجھتا ہے کہ تمہا رے لئے کس قدر دیر منا سب ہے.لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو اس وقت بھی طلا ق دے دو جبکہ تم نے ان کو چھوا تک نہ ہو.یامہر نہ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً١ۖۚ وَّ مَتِّعُوْهُنَّ١ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ مقرر کیا ہو.اور (چاہیے کہ اس صورت میں) تم انہیں مناسب طور پر کچھ سامان دو.(یہ امر) دولت مند پر اس کی طاقت وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ١ۚ مَتَاعًۢا بِالْمَعْرُوْفِ١ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ۰۰۲۳۷ کے مطابق (لازم ہے) اور نادار پر اس کی طاقت کے مطابق (ہم نے ایسا کرنا) نیکوکاروں پر واجب کر دیا ہے.حلّ لُغا ت.اَلْمُوْ سِعُ اَوْسَعَ سے اسم فا عل ہے.اور اَوْسَعَ الرَّجُلُ کے معنے ہیں صَارَ ذَا سَعَۃٍ وَ غِـنًی وہ آدمی وسعت والا ہو گیا.یا غنی ہو گیا.اور اَوْسَعَ اللّٰہُ عَلٰی فُلَانٍ کے معنے ہیں اَغْنَاہُخدا تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا.( اقرب)
Page 379
اَلْمُقْتِرِ اَقْتَرَسے اسم فا عل ہے.اور اَقْتَرَ عَلیٰ عَیَالِہٖ کے معنے ہیں قَلَّ مَا لُہٗ وَافْتَقَرَ اُ س کا مال کم ہوگیا اور وہ محتا ج ہو گیا.اور اَقْتَرَ اللّٰہُ رِزْقَہٗ کے معنے ہیں ضَیَّقَہٗ وَ قَلَّلَہٗ.اللہ تعالیٰ نے اس کا ما ل کم کر دیا اور اسے تنگ دست کر دیا.(اقرب) تفسیر.اب طلاق کے متعلق اللہ تعالیٰ بعض اور احکا م بیا ن فر ما تا ہے.طلاق کی پہلی صورت تو یہ تھی کہ میاں بیوی میں کو ئی شدید اختلا ف پیدا ہوا اور طلاق وا قع ہو گئی.مگر بعض ایسی بھی عورتیں ہو تی ہیں کہ میاں بیوی ابھی اکٹھے بھی ہو نے نہیں پا تے کہ طلاق وا قع ہو جا تی ہے.مثلاً نکا ح کے معًا بعد ایسے گوا ہ مل گئے جنہوں نے ایسی گوا ہیا ں دیں جن سے نکاح کی حر مت ثا بت ہو گئی یا کم سے کم نکا ح کی کر اہت پیدا ہو گئی.مثلاً ادھوری گوا ہی ایسی مل گئی کہ یہ عورت خا وند کی رضا عی بہن ہے.پس گووہ ادھوری گوا ہی ہو مگر خا وند کے دل میں کرا ہت تو پیدا ہو جائے گی اور اس قسم کی گوا ہیا ں بعض دفعہ نکاحوں کے بعد مل جا تی ہیں.پس ایک صورت تو یہ ہے جس میں چھونے سے بھی پہلے طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جا تی ہے.اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ نکا ح کے بعد دونوں خا ندانوں کے بعض اکا بر جن کو پہلے اس تعلق کا علم نہ ہوا ہو فیصلہ دے دیں کہ ہما رے آ پس کے تعلقا ت ایسے ہیں کہ تم دونو ں آپس میں نبھا نہیں کر سکو گے.اس لئے بہتر ہے کہ عورت کو طلاق دے دو اور وہ چھونے سے پہلے اُسے طلا ق دے دے.اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً سے پتہ لگتا ہے کہ ایسا نکاح جس میں کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو وہ بھی جائزہوتا ہے لیکن جیسا کہ اسلامی فقہاء نے تصریح کی ہے خواہ مہر کی تعیین نہ کی گئی ہو یہ ضرورسمجھا جائےگا کہ مہر مقرر ہے اور اس کی تعیین مہر بالمثل سے کی جائےگی.یعنی اسی حیثیت کے خاندان کے دوسرے افراد کو دیکھا جائےگا کہ اُن کا کیا مہر ہے؟ اور وہی مہر اس عورت کا قرار دیاجائےگا.(الھدایۃ شرح البدایۃ کتاب النکاح باب المہر).اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتاہے کہ مَتِّعُوْهُنَّ١ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ١ۚ مَتَاعًۢا بِالْمَعْرُوْفِ١ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ.اگر تم عورتوں کو اُن کے چھونے سے پہلے طلاق دے دو یا ایسی صورت میں طلاق دو کہ تم نے اُن کا مہر مقرر نہ کیا ہو تو دونوں صورتوں میں تمہارا فرض ہو گا کہ تم اُن سے حسنِ سلوک کرو اور انہیں مناسب رنگ میں کچھ سامان دے دو.مالی وسعت رکھنے والا اپنی طاقت کے مطابق اس کام میں حصہ لے اور تنگدست اپنے حالات کو مدنظر رکھ کر حصہ لے اور یہ صرف طوعی نیکی نہیں بلکہ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ نیکی اور تقوٰی سے کام لینے والوں پر ہم نے یہ واجب کر دیا ہے کہ وہ عورتوں کو حسن سلوک کے ساتھ رخصت کریں.
Page 380
احادیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری نے ایک عورت سے شادی کی مگر اس کا مہر مقرر نہ کیا.ثُمَّ طَلَّقَھَا قَبْلَ اَنْ یَمَسَّھَا.پھر مجامعت سے قبل اُسے طلاق دےدی.جب یہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اُس سے پوچھا کہ کیا تم نے احسان کے طور پر اسے کوئی چیز بھی دی ہے اُس نے کہا.یا رسول اللہ ! میرے پاس تو کچھ بھی نہیں.آپ نے فرمایا.مَتِّعْھَا بِقَلَنْسُوَتِکِ اگر تمہارے پاس اور کوئی چیز نہیں تو اپنی ٹوپی ہی اُتار کر اس کے حوالے کردو.(تفسیربحرمحیط زیر آیت ھٰذا) اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کس قدر حکم ہے.کہ اگراور کوئی چیز نہ ہو تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ٹوپی یاپگڑی ہی اُتار کر اُسے دے دے اور خالی ہاتھ نہ جانے دے.لیکن اگر اس بارے میں کوئی جھگڑا پیدا ہوتو چونکہ قرآن کریم نے اصولی طور پرفیصلہ فرما دیا ہے کہ جھگڑے کی صورت میں اولی الامر کی طرف رجوع کیا کرو.اس لئے اختلاف کی صورت میں قاضی کے پاس فیصلہ لے جانا چاہیے وہ حالات دیکھ کر فیصلہ دے گا کہ خاوندنے اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو اُس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں؟ وَ اِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ اور اگر تم انہیں قبل اس کے کہ تم نے انہیں چھوا ہو لیکن مہر مقرر کر دیا ہو طلاق دے دو تو (اس صورت میں ) لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ جو مہر تم نے مقرر کیا ہو اس کا آدھا (ان کے سپرد کرنا) ہوگا.سوائے اس (صورت)کے کہ وہ (یعنی عورتیں ) معاف يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ١ؕ وَ اَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ کر دیں یا وہ (شخص) معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح (کا) باندھنا ہو.اور تمہارا معاف کر دینا تقویٰ کے لِلتَّقْوٰى ١ؕ وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا زیادہ قریب ہے.اور تم آپس میں (معاملہ کرتے وقت) احسان کو نہ چھوڑا کرو.(اور یاد رکھو) کہ جو کچھ تم کرتے ہو
Page 381
ہونے کا ذکر نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کُتب کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے.ورنہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کیوں غصّہ آتا.اگر قرآن کریم کی آیات منسوخ ہو گئی تھیں تو اس پر انہیں کیوں غصہ آتا.ان کی دشمنی صاف بتا رہی ہے کہ چونکہ قرآن کریم نے ان کی کتابوں کو منسوخ کر دیا تھا.اس لئے وہ ناراض ہو گئے.پس پہلی آیت میں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں کے منسوخ کئے جانے کاہی ذکر ہے.اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُىِٕلَ مُوْسٰى کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح (اس سے) پہلے موسیٰ ؑسے سوال کئے گئے تھے مِنْ قَبْلُ١ؕ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ اور (بھول جاتے ہو کہ) جو شخص کفر کو ایمان سے بدل لے تو سمجھو کہ وہ سیدھے سَوَآءَ السَّبِيْلِ۰۰۱۰۹ راستے سے بھٹک گیا.حلّ لُغات.تَبَدَّ لَ.یہ باب تَفَعُّل سے ہے.اور باب تَفَعُّل کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو اختیار کرلینے کے معنے ہوتے ہیں اس لئے مَنْ یَّتَبَدَّلْ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی ایمان چھوڑ کر اس کے بدلہ میں کفر لے لیتا ہے.(اقرب) ضَلَّ.دو طریق پر استعمال ہوتا ہے (۱) ضَلَّ الطَّرِیْقَ(۲) ضَلَّ عَنِ الطَّرِیْقِ.اسے راستہ نہ ملا.یا بھول گیا(اقرب) اسی طرح ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِیْلِ اور ضَلَّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِیْلِ آتا ہے.سَوَآءَ کے معنے ہیں سیدھا اور مستقیم جس میں کوئی کجی نہ ہو.پس معنے یہ ہوئے کہ درست یا صحیح راستہ سے جس میں کوئی کجی نہ ہو وہ گمراہ ہو گئے یا اُسے بھول گئے.(المنجد) تفسیر.نادان عیسائی مصنف اعتراض کیا کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نعوذ باللہ اپنی کم علمی چھپانے کے لئے صحابہؓ کو سوال کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے.لیکن قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ صحابہؓ کو سوال کرنے سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں جیسے سوال کرنے سے روکا گیا تھا.
Page 382
اُس کے رشتہ داروں نے روانہ کی تھی.جس طرح ہمارے ملک میں ایک بے تکلّف نوکر ساتھ جاتی ہے تاکہ اُسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو.چونکہ یہ عورت حسین مشہور تھی اوریو ں بھی عورتوں کو دلہن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے مدینہ کی عورتیں اس کو دیکھنے گئیں اور اس عورت کے بیان کے مطابق کسی عورت نے اُس کو سکھا دیا کہ رُعب پہلے دن ہی ڈالا جاتا ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم تیرے پاس آئیں تو کہہ دیجیئوکہ میں آپ سے اللہ کی پنا ہ مانگتی ہوں، اِس پر وہ تیرے زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے.اگر یہ بات اس عورت کی بنائی ہو ئی نہیں تو کچھ تعجب نہیں کہ کسی منافق نے اپنی بیوی یا اور کسی رشتہ دار کے ذریعہ یہ شرارت کی ہو.غرض جب اس کی آمد کی اطلاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ اس گھر کی طرف تشریف لے گئے جو اس کے لئے مقرر کیا گیا تھا.احادیث میں لکھا ہے.کہ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَیْھَا النَّبِیُّ صَلَّی اللّہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ ھِــبِیْ نَفْسَکِ ِلِیْ قَالَتْ وَ ھَلْ تَھَبُ الْمَلِکَۃُ نَفْسَھَا لِلسُّوْقَۃِ ؟ قَالَ فَاَھْوٰی بِیَدِہٖ یَضَعُ یَدَہٗ عَلَیْھَا لِتَسْکُنَ فَقَالَتْ اَعُوْذُ بِاللّہِ مِنْکَ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ.ثُمَّ خَرَجَ عَلَیْنَافَقَالَ یَا اَبَا اُسَیْدٍ اُکْسُھَا رَازِ قِیَّیْنِ وَاَلْحِقْھَا بِاَھْلِھَا(بخاری کتاب الطلاق باب من طلق و ھل یواجہ الرجل امرأتہ بالطّلاق)جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم اس کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اُسے فرمایاکہ تو اپنا نفس مجھے ہبہ کر دے اُس نے جواب دیا کہ کیا ملکہ بھی اپنے آپ کو عام آدمیوں کے سپرد کیا کرتی ہے؟ ابو اُسید کہتے ہیں کہ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اِس خیال سے کہ اجنبیت کی وجہ سے گھبرا رہی ہے اُسے تسلی دینے کے لئے اس پر اپنا ہاتھ رکھا.آپ نے اپنا ہاتھ ابھی رکھاہی تھا کہ اُس نے یہ نہایت ہی گندہ اور نامعقول فقرہ کہہ دیاکہ میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں.چونکہ نبی خدا تعالیٰ کا نام سُن کر ادب کی رُوح سے بھر جاتا ہے اور اُس کی عظمت کا متوالا ہوتا ہے.اُس کے اِس فقرہ پر آپ نے فوراً فرمایا کہ تو نے ایک بڑی ہستی کا واسطہ دیا ہے اور اس کی پناہ مانگی ہے جو بڑا پناہ دینے والا ہے اس لئے میں تیری درخواست کو قبول کرتاہوں.چنانچہ آپ اُسی وقت باہر تشریف لے آئے اور فرمایا.اے ابا اسیدؓ! اِسے دو چادریں دے دو اور اسے اِس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو.چنانچہ اس کے بعد اُسے مہر کے حصہ کے علاوہ بطور احسان دو رازقی چادریں دینے کا آپ نے حکم دیا تا کہ قرآن کریم کا حکم وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ پورا ہو.جو ایسی عورتوں کے متعلق ہے جن کو بلا صحبت طلاق دے دی جائے اور آپ نے اُسے رخصت کردیا اور ابو اسیدؓ ہی اُس کو اُس کے گھر پہنچا آئے.اُس کے قبیلہ کے لوگوں پر یہ با ت نہایت شاق گذری اور انہوں نے اُس کو ملامت کی مگر وہ یہی جواب دیتی رہی کہ یہ میری بد بختی ہے اور بعض دفعہ اُس نے یہ بھی کہا کہ مجھے ورغلایا گیا تھااور کہا گیا تھا کہ جب رسو ل کریم صلی اللہ علیہ و سلم تیرے پاس آئیں تو تم پرے ہٹ
Page 383
جانا.اور نفرت کا اظہار کرنا اس طرح اُن پر تمہارارعب قائم ہو جائےگا.معلوم نہیں یہ وجہ ہوئی یا کوئی اور بہر حال اُس نے نفرت کا اظہارکیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم اس سے علیحدہ ہوگئے اور اُسے رخصت کر دیا.اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مَسّ سے مراد صرف چھونا نہیں بلکہ مخصوص تعلقات کا قائم ہوجانا ہے.ورنہ لغوی معنوں کے لحاظ سے تورسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اُس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور آپ اُسے چھو چکے تھے.اِلَّاۤ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ کے متعلق بھی اختلاف ہوا ہے کہبِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِسے کون مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں اس سے خاوند مراد ہے (کشاف) کیونکہ نکاح ہو جانے کے بعد اُس کی گرہ خاوند کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس صورت میں خاوند کا عفو کرنا یہ ہوگا کہ وہ نصف مہر کی بجائے سارا مہر دےدے لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورت کے ولی ہیں (کشاف) اور ان کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہیںتونصف مہربھی نہ لیں.اُن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ اِس طرح ہوتی ہے کہ کسی عورت کا نکاح اُس وقت تک نہیں ہو سکتاجب تک کہ اس کے ولی اجازت نہ دیں.بعض لوگوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ اِس سے خاوند مراد نہیں ہو سکتا.کیونکہ اس نے تو مہر دینا ہے اور دینے کو معاف کرنا نہیں کہتے(رازی ).لیکن ان کا یہ اعتراض عربی زبان سے نا واقفیت پر دلالت کرتا ہے اس لئے کہ عفوکے معنے زیادہ دینے کے بھی ہوتے ہیںچنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں عَفَا فُلَانُ الشَّعْرَ (لسان)اور اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ فلاں شخص نے بال بڑھالئے ہیں.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے اِعْفُو اللُّحٰی (مسلم کتاب الطہارۃ باب خصال الفطرۃ) اور اس کے معنے ہیں.ڈاڑھیا ں بڑھاؤ.پھر عرب کے رسم ورواج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مہر پہلے دے دیا کرتے تھے.پس خاوند کاعفو کرنا یہ ہوگاکہ وہ باقی نصف واپس نہ لے.اس لحاظ سے اس کے معنے یہ ہوئے کہ طلاق دیتے وقت یا تو کچھ بڑھا کر دویا یہ کہ آدھا جو تم دے چکے ہو وہ بھی واپس نہ لو.اور پہلے لوگ یہ دونوں معنے مراد لیتے آئے ہیں.چنانچہ قاضی شریح کہتے ہیں اَنَا اَعْفُوْاعَنْ مُھُوْر بَنِیْ مُرَّۃَ وَ اِنْ کَرِھْنَ کہ میں اپنی قوم بنی مرّہ کی عورتوں کا مہر معاف کردوںگا.اگرچہ وہ نا پسند ہی کرتی رہیں.(بحر محیط زیر آیت ھذا)دراصل یہاں عورت کی کراہت یا عدمِ کراہت کا کوئی سوال نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر عورت اس قابل نہ ہو کہ معاف کر سکے، مثلاً ایسی بالغ نہ ہو جس کو مال پر تصّرف حاصل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر ولی عفو کا اعلا ن کر دے تو یہ عورت کا ہی اعلان سمجھا جائےگا.اس کے متعلق عورت سے الگ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی.اسی طرح جبیربن مطعم ایک صحابی ہیں.اُن کا ایک عورت سے نکاح ہوا جب انہوں نے اسے طلاق دی تو جو
Page 384
کچھ مہر تھا اُسے دے دیا اور پھر اس سے بھی زیادہ دیا.اور کہا اَنَا اَحَقُّ بِالْعَفْوِ کہ میں عفو کرنے کا زیادہ حقدار ہوں.گویازیادہ دینے کوانہوں نے عفو قرار دیا.(کشاف زیر آیت ھذا).وَ اَنْ تَعْفُوْۤا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی میں مردعورت ولی سب مراد ہیں.اور یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پر اپنا حق چھوڑنابہ نسبت اپنا حق طلب کرنے کے زیادہ افضل ہوتا ہے اور تقویٰ کا یہی تقاضاہوتاہے.مگر افسوس ہے کہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور ہمیشہ اپنے حقوق کا مطالبہ پیش کرتے اور اس پر لڑتے جھگڑتے ہیں.دوسرے پر احسان کرنے کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھاتے حالانکہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے کہ تمہارا معاف کردینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے.یعنی عورت یہ خیال کرے کہ میں اپنے خاوند کے ہاں آباد تو ہوئی نہیں.اگر اسے مہر معاف کردوں تو کیا حرج ہے؟اسی طرح مرد یہ خیال کرے کہ گویہ عورت میرے ہاں آباد نہیں ہوئی لیکن میری طرف منسوب تو ہوئی ہےاس لئے میں ہی کچھ زیادہ دے دوں.اِسی طرح ولی کو چاہیے کہ وہ ایسے رنگ میں فیصلہ کرائے کہ کوئی فتنہ پیدا نہ ہو.وَ لَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ میں نسیان کے معنے بھولنے کے نہیں بلکہ چھوڑنے کے ہیں.جیسے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے کہ نَسُوا اللّٰہَ فَنَسِیَھُمْ (التوبۃ: ۶۷) انہوں نے اللہ کو چھوڑدیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اُن کو ترک کر دیا.اور فضل سے مراد ایسا فعل ہے جس سے انسان دوسرے پر فضیلت حاصل کر لے.پس لَاتَنْسَوُاالْفَضْلَ بَیْنَکُمْ میں اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ آپس میں معاملہ کرتے وقت تم میں سے ہر فرد کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نیکی اور احسان اور مروّت میں ایک دوسرے پر فضیلت لے جائے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے.اِنَّ اللّٰہَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ.اللہ تعالیٰ تمہارے کاموںکو دیکھتا ہے وہ تمہاری نیکی ضائع نہیں کرے گا بلکہ تمہیں اس کا اچھے سے اچھا بدلہ دےگا.پس چاہیے کہ تم ان احکام کو ملحوظ رکھواور ان پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو.حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ١ۗ وَ قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ۰۰۲۳۹ تم (تمام) نمازوں کا اور( خصوصاً )درمیانی نماز کا پورا خیال رکھو.اور اللہ کے لئے فرمانبردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ.حلّ لُغات.اَلْقُنُوْتُ کے معنے ہیں اَلطَّاعَۃُ اطاعت.اَلْقِیَامُ فِی الصَّلٰوۃِ نماز کے لئے کھڑا
Page 385
ہونا.اَلدُّعَاءُ دُعا.اَلْخُشُوْعُ وَخَفْضُ الْجَنَاحِ وَسَکُوْنُ اْلاَطْرَافِ وَ تَرْکُ الْاِلْتِفَاتِ مِنْ رَھَبِ اللّٰہِ.اللہ تعالیٰ کے خوف سے کامل عجزوانکساراور ادب اور سکون اور ماسوی اللہ کو بھُلا کر کام کرنا.(اقرب) تفسیر.شادی بیاہ کے ذکر کے سلسلہ میں اب اللہ تعالیٰ نمازوںکا ذکر فرماتا ہے کیونکہ بالعموم شادی کی وجہ سے لوگ نمازوں میں بہت کچھ سُست ہو جاتے ہیں وہ اوّل تو رات کو زیادہ دیر بیدار رہتے ہیں جس کی وجہ سے تہجداور فجر کی باجماعت نمازمیں ان سے غفلت ہو جاتی ہے.اور پھر دن کو بھی گھریلو مصروفیات انہیں نمازوںکی طرف توجہ کرنے نہیں دیتیں.پس چونکہ شادی کے سِلسلہ میں عبادت میں بہت کچھ نقص واقع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کے مشاغل بڑھ جاتے ہیںکیا بلحاظ آپس کے تعلقات کے اور کیا بلحاظ بچوں کی دیکھ بھال کے اور کیا بلحاظ سامانِ خوردونوش وغیرہ مہیّا کرنے کے اِسی طرح طہارت کے نقائص بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے فرمایا کہ تمہاری گھریلو مصروفیات بے شک بڑھ جا ئیںگی.تمہیں روزی کمانے کے لئے پہلے سے زیادہ تگ و دَو کرنی پڑےگی اور تمہاری توجہ میں یکسوئی نہیں رہے گی.مگر دیکھنا تم نمازوں میں سُستی نہ کرنا خصوصاً نماز وسطیٰ کا ہمیشہ خیال رکھنا.یہ نمازوسطیٰ کونسی ہے؟ اس کے متعلق لوگوں میں بہت کچھ اختلاف پاتا جاتا ہے.(۱) بعض نے اسے تہجد کی نماز قرار دیا ہے اور میرا خیال بھی نماز تہجدکی طرف ہی جاتا ہے.جو شام اور صبح کے درمیان آتی ہے.(۲) بعض کہتے ہیںکہ صلوٰۃوسطیٰ سے وہ نماز مراد ہے.جو کام کے درمیان آجائے(کشاف و بحر محیط زیر آیت ھذا).اِس کے علاوہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم نے عصرکی نمازکوبھی صلوٰۃ وسطیٰ قراردیا ہے.چنانچہ ترمذی اور بخاری میں سمرۃؓ سے روایت آتی ہے کہ جنگِ احزاب میں جب کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کو عصر کی نماز سے روکاتو آپ نے فرمایا.خدا ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرے انہوں نے ہمیں صلوٰۃ وسطیٰ سے روک دیا ہے.(ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورۃ البقرۃ وبخاری کتاب التفسیر باب حفظوا علی الصلوات زیر آیت ھذا) مگر میرے نزدیک اِن حدیثوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے وہی نماز مراد ہے جو کام کے درمیان آجائے کیونکہ جنگِ احزاب میں بھی عصر کی نماز دوران جنگ میں آگئی تھی.اور ممکن ہے اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے اسے صلوٰۃوسطیٰ قرار دیا ہو.وسطیٰ کے معنے افضل واعلیٰ کے بھی ہوتے ہیں(کشاف زیر آیت ھذا).اس لئے جس نماز کو انسان زیادہ مشاغل ترک کر کے پڑھے وہی نماز اس کے لئے صلوٰۃوسطیٰ ہو گی اور اُس کے لئے زیادہ برکات اور انوار کی حامل ہوگی.اس مفہوم کو مدّ نظر رکھتے ہوئے اوپر کے معنوں کی تائید ہوتی ہے.
Page 386
میر ے نزدیک حٰفِظُوْا میںایک اور امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے.حٰفِظُوْا باب مفا علہ سے ہے جس میں اشتراک پا یا جا تا ہے.پس اس میں خدا تعالیٰ نے مر د و عورت دونو ں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اب نکا ح کے بعد تم آپس میں میاں بیوی بن گئے ہو.تم دونوں مل کر نما زوں کے متعلق ایک دوسرے کی نگرانی کر و.خصوصاً نما ز وسطیٰ یعنی تہجد کے متعلق.چنا نچہ حدیث میں آ تا ہے کہ اگر تہجد کے نما ز کے لئے خا وند کی آ نکھ کھلے تو بیوی کو جگا دے اور اگر وہ نہ اٹھے تو پا نی کا ایک ہلکا سا چھینٹا اس کے منہ پر مارے.اور اگر بیوی کی آ نکھ کھلے تو وہ میاں کو جگا دے اور اگر وہ نہ اُٹھے تو وہ بھی پا نی کاایک ہلکا سا چھینٹا اس کے منہ پر مارے(مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب التحریض علی قیام اللیل).جب تہجد کی نما ز کے لئے رسول کر یم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس قدر تا کید فر ما ئی ہے تو اور نما زوں کی نگہداشت کا حکم خود بخود وا ضح ہو گیا.پس گو محا فظت کے معنے عا م طور پر نگرا نی کے ہو تے ہیں مگر دراصل اس میں وہ خا صہ ملحوظ ہے جو باب مفا علہ کا ہے اور جس کی رو سے اس کا یہ مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی نگرا نی کریں.اور عبا دت میں ایک دوسرے کے لئے تر قی کا مو جب بنیں.قُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ کے معنے یہ ہیں کہ نما ز میں تمہارا خیال کسی اور طرف نہ ہو بلکہ پورے خلو ص اور اطا عت اور تبتل تا م کے سا تھ اللہ تعالیٰ کی عبا دت کرو.اس حکم کے نازل ہو نے سے پہلے صحا بہ ؓ بعض دفعہ نما ز میں آپس میں بات چیت بھی کر لیا کر تے تھے مگر پھر اس حکم کے نتیجہ میں انہو ں نے خا موشی اختیار کر لی.(ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورۃ البقرۃ) فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا١ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اور اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو نے کی حالت میں (ہی نماز پڑھ لو) پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ۰۰۲۴۰ کویاد کرو کیونکہ اس نے تمہیں (وہ کچھ )سکھایا ہے جو تم (پہلے )نہ جانتے تھے.تفسیر.اس آ یت میں نما ز کی اہمیت پر زیا دہ زور دینے کےلئے فر مایا میاں بیوی کے تعلقات کیا چیز ہیں؟ اگر تمہا رے پیچھے تمہیں پکڑ نے کیلئے کو ئی دشمن آ رہا ہو اور تم بھا گ رہے ہو تو خواہ تم سوار ہو یا پیا دہ تو بھی تم نما ز کو نہ چھو ڑو بلکہ اسی حا لت میں ہی پڑھ لو.گو یا نماز میں غفلت اور سستی کسی صورت میں بھی جا ئز نہیں.حتیّ کہ سخت
Page 387
خطرہ کی حا لت میں بھی جو صلوٰ ۃ الخو ف کے خطرہ سے بھی بڑھ کر ہوجو عین جنگ میں ہو تی ہے تمہا رے لئے یہ جائز نہیں کہ تم نما ز چھوڑ دو بلکہ جس حالت میں بھی ہو نما ز ادا کرو.چنا نچہ بخا ری میں حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان سے صلوٰۃ خو ف کے متعلق سوال کیا گیا.تو انہوں نے اس کا طر یق بتایا اور پھر فر ما یا کہ اگر اس سے بھی زیادہ خو ف کی حا لت ہو تو پھر پیدل یا سوارجس حا لت میں بھی ہو تم نما ز پڑ ھ لو.اور حضرت نا فع جو اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوںحضرت عبد اللہ بن عمر ؓ نے یہ با ت رسول کر یم صلی اللہ علیہ و سلم سے ہی سُنی ہے.( بخا ری کتا ب التفسیر باب قولہ وَ اِنْ خِفْتُمْ) اس سے معلو م ہو تا ہے کہ خود رسول کر یم صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی اس آیت میں صلوٰ ۃ خو ف وا لی حالت سے بھی زیا دہ خطرہ والی حا لت مرا د لی ہے، صلوٰۃ خو ف میں تو با قا عدہ ایک امام کی اقتداء میں نما ز ادا کی جا تی ہے (النساء: ۱۰۳)مگر یہ حا لت ایسی ہے جس میں اتنی مہلت بھی نہ مل سکے اور دوڑتے اور بھا گتے ہو ئے نما ز پڑ ھنی پڑ ے.مثلاً اسلا می فو ج کا ایک سپا ہی دشمن کے حالا ت معلو م کر نے کے لئے گیا تھا.اس کا دشمن کو علم ہو گیا.وہ گھو ڑے کو دوڑا تا ہوا واپس آ رہا ہے اور پچا س سا ٹھ سپا ہی اس کے تعاقب میں ہیں.کہ راستہ میں نما ز کا وقت آ گیا.اب اگر وہ ٹھہر جا تا ہے یا گھو ڑے سے اُتر کر نما ز پڑھنے لگ جا تا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ پکڑا جا ئےگا اور اسلا می لشکر ان معلو مات سے محروم رہ جائےگا جن کو مہیّا کر نے کے لئے اُسے بھجوا یا گیاتھا.پس چو نکہ اس کا جا ن بچا کر اسلا می لشکر میں پہنچنا ضر وری ہے.اس لئے اسے اجا زت ہو گی کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتا چلا جا ئے.جس طرح بیمار آدمی لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیتا ہے یا بعض دفعہ اشاروں میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے اسی طرح اسے بھی اجازت ہوگی کہ جس طرح چاہے نما ز پڑ ھ لے.مثلاً گھو ڑا دوڑاتےدوڑاتے نما ز کے کلما ت دہراتا جائے.رکو ع کا وقت آ ئے تو ذرا سا سر جھکا لے اور ایک دو دفعہ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْم کہہ دے.ذرا اور سر جھکا دے تو اسے سجدہ سمجھ لے.اس طرح جلدی جلدی نما ز پڑھ کر فا رغ ہو جا ئے.ایسی حالت میں با وجو د اس کے کہ اس کی ایک ٹا نگ گھو ڑے کے ایک طرف ہو گی اور دوسری ٹا نگ دوسری طرف پھر بھی اس کی نماز ہو جائےگی.اور اگر اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہو گا تب بھی نما ز ہو جا ئے گی.ہاں! اگر مو قعہ مل سکے تو نماز شروع کر تے ہو ئے قبلہ کی طرف مُنہ کر لیا جا ئے.پھر خوا ہ کسی طرف مُنہ ہو جا ئے.غرض خو ف کے وقت نما ز کو اپنی مقررہ شکل سے بدل کر پڑھنا جا ئز ہے.چا ہے انسا ن گھو ڑے پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لے.چا ہے اشارے سے پڑھ لے.یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دشمن کے سا منے بندوق تا نے کھڑا ہو.اور نما ز کا وقت آ جا ئے.ایسی صورت میں اُ س کے لئے جائز ہو گا کہ وہ بندوق بھی سنبھا لے رکھے دشمن پر فا ئر بھی کر تا جا ئے اور نما ز کی عبا رتیں بھی دہر اتا جا ئے.بلکہ یہ نما ز خو ف کی
Page 388
حالت میں شہروں میں رہتے ہو ئے بھی پڑھی جا سکتی ہے.مثلاً فر ض کرو ایک ملک کی دوسرے ملک سے لڑائی ہو جا تی ہے اُس وقت سر حدی شہر وں یا دیہات میں رہنے والے جو لو گ ہوںگے اُن کے لئے جا ئز ہو گا کہ اگر زور کا حملہ ہو تو وہ کھڑے کھڑے نما ز کی عبارتیں دہراتے جا ئیں اور سا تھ ہی دشمن پر گولیا ں بر ساتے جائیں.فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.ہا ں جب خو ف کی حالت جا تی رہے اور تم امن میں آ جا ؤ تو پھر تمہیں اسی طر ح نما ز پڑھنی چا ہیے جس طرح قُوْمُوْالِلّٰہِ قٰنِتِیْنَ میں حکم دیا گیا ہے یعنی خا مو شی اور بغیر ضروری حر کت کے.كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ کے معنے ہیں جس طر ح اس نے تم کو سکھا یا ہے یا اس لئے یاد کر و کہ اس نے تمہیں وہ کچھ سکھا یا ہے جو تم پہلے نہ جا نتے تھے.اِن الفا ظ میں قرآن کریم نے دنیا کے سا منے یہ دعوٰی پیش کیا ہےکہ اس کتا ب کے ذریعے لو گوں کو وہ روحانی علو م سکھا ئے گئے ہیں جو اس سے پہلے اور کسی مذ ہب کی الہا می کتا ب نے بیان نہیں کئے.وَ الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا١ۖۚ وَّصِيَّةً اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لِّاَزْوَاجِهِمْ۠ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ١ۚ فَاِنْ حق میں ایک سال تک فائدہ پہنچانےیعنی ان کو (گھروں سے) نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں.خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ لیکن اگر وہ (خود بخود) چلی جائیں تو وہ اپنے متعلق جو پسندیدہ بات کریں اس کا تمہیں کوئی گناہ نہیں.مِنْ مَّعْرُوْفٍ١ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۰۰۲۴۱ اور اللہ غالب (اور )حکمت والا ہے.تفسیر.وَ صِیَّۃٌ مصدر ہے اور اس سے پہلے یُوْ صُوْنَ محذوف سمجھا جائےگا.یعنی وہ وصیت کر جا ئیں.مَتَا عًا دوسرا مصدر ہے اس سے پہلے بھی اَنْ مَتِّعُوْ ھُنَّ محذوف ہے.اور معنے یہ ہیں کہ اپنی بیو یو ں کے حق میں
Page 389
وصیت کر جا ئیں کہ بعد میں وہ لو گ جن کے ہا تھ میں وصیت کا اجراء ہے انہیں ایک سا ل تک فا ئدہ پہنچا ئیں.اس کے بعد غَیْرَ اِخْرَاجٍ کے الفا ظ ہیں.جو بدل ہیں مَتَا عًا کا پس معنٰی یہ ہو ئے کہ فا ئدہ پہنچا نے سے ہما ری مراد یہ ہے کہ ان کوگھروں سے نہ نکا لیں(املاء مامنّ بہ الرحمٰن).بلکہ با و جو د اس کے کہ مکا ن کسی اور وا رث کے حصّہ میں آ یا ہو بیو یو ں کو ایک سال تک اس میں رہنے کا حق حا صل ہے.اس کے یہ معنے نہیں کہ عورت خو د بھی مکا ن سے نہیں جا سکتی.عورت عدت کے بعد اپنی مر ضی سے اور اپنے فا ئد ہ کے لئے جا نا چا ہے تو جا سکتی ہے.سال بھر کی شرط صرف عورت کے آرام اور فا ئدہ کے لئے لگا ئی گئی ہے اور اس سے وارثوں کو پا بند کیا گیا ہے.عورت پر پا بندی صرف ایا م عدت تک گھر میں رہنے کی ہے بعد میں اس حکم سے فا ئدہ اٹھانا یا نہ اٹھا نا اس کے اختیار میں ہے.یہ امر کہ اس ایک سال میں عدّت شا مل ہے یا نہیں.اس بارہ میں اختلا ف پا یا جا تا ہے لیکن میر ے نزدیک جس با ت میں عورت کا فا ئدہ ہو اسے تسلیم کر نا چا ہیے اور وہ صورت یہی ہے کہ عدت کے بغیر ایک سال تک عورت کو گھر میں رہنے دیا جائے.مگر افسوس ہے کہ اس حکم کی پا بندی نہ تو مر نے والے کے رشتہ دار کر تے ہیں اور نہ عورتیں.اگر تو عورت کے بچے ہو ں تو پھر تورشتہ دار کچھ عر صہ تک صبر کر تے ہیں لیکن اگر بچے نہ ہوں تو چند ماہ کے بعد ہی مر نے والے کےرشتہ دار مکا ن اور جا ئداد کی تقسیم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں حا لا نکہ اس مکا ن میں ایک سال تک عورت کو رہنے دینا ضروری ہو تا ہے.اور اللہ تعا لیٰ نے اس کی سخت تا کید فر ما ئی ہے.بعض نے کہا ہے کہ یہ آ یت احکا م میراث کے ذریعہ منسوخ ہو گئی ہے(رازی زیر آیت ھذا) مگر یہ بالکل غلط ہے بیوہ کا اپنے خا وند کی جائیداد میں جو حصّہ رکھا گیا ہے اس کے سا تھ اس کا کو ئی تعلق نہیں یہ ایک الگ حکم ہے جس میں جا ئیداد کے حصہ کے علا وہ عورت کےلئے سال بھر کے نان و نفقہ اور رہا ئش کا انتظام ضروری قرار دیا گیا ہے.فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ میں بتا یا کہ ہما را یہ منشاء نہیں کہ تم ایک سال تک ان کو پکڑکر رکھو بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہا ری طرف سے ایک سال کے عرصہ تک انہیں کھلی اجا زت ہو نی چاہیے کہ وہ آ زادانہ طور پر اپنے گھر میں رہیں ہا ں اگر وہ سال کے اندر ہی مکا ن چھوڑ دیں تو تم انہیں جا نے دو.عدّت میںتو خو د ان کا نکلنا بھی ممنو ع ہے لیکن اس کے بعد ان کا خود نکلنا گناہ نہیں.پس اس آ یت کو آ یت عدت سے منسوخ سمجھنا بھی غلطی ہے.یہ ان سے نیک سلوک کر نے کا ایک زائد حکم دیاگیا ہے.کیو نکہ فوراً ان کا نیا گھر بنا نا یا نکاح کرنا مشکل ہو تا ہے چا ر ماہ دس دن تک تو وہ خود نہیں نکل سکتیں.اس کے بعد ایک سال مزید تک ان کو نکا لا نہیں جا سکتا ہا ں وہ خود چا ہیں تو نکل سکتی ہیں کیو نکہ اللہ تعا ٰلیٰ نے ان کے فعل کو معروف کہا ہے.
Page 390
معروف کا لفظ قر آ ن کر یم میں بہت دفعہ آ یا ہے.یہ عُرف سے نکلا ہے اورا س کے معنے ہیں پہچا نا ہوا.مفردات امام راغب میں لکھا ہے.اَلْمَعْرُوْفُ اِسْمٌ لِکُلِّ فِعْلٍ یُعْرَفُ بِالْعَقْلِ وَا لشَّرْعِ حُسْنُہٗ یعنی معروف ہر اس فعل کو کہتے ہیں جس کی خوبی عقل و شرع سے پہچا نی جائے.پس جب کو ئی فعل شرع کے لحا ظ سے معروف ہو تو وہ مطا بق قا نو ن فعل کہلائےگا.اور جب عقل عامہ سے اس کی خو بی پہچا نی جا ئے تو اسے مطا بق دستور کہیں گے کیو نکہ جس امر کی خو بی ہر انسا ن پہچا نتا ہے اس کا رواج بنی نوع انسا ن میں پا یا جاتا ہے اور جب کسی امر کی خو بی کسی خا ص فر د کی عقل سے پہچا نی جائےگی تو اسے منا سب حا ل یا مطا بق حال کہیں گے کیو نکہ افراد کے سا تھ انہی نیکیوں کا تعلق ہوتا ہے جو خا ص ان کے حا لات سے متعلق ہوں.پس معروف کے معنے قا نون یا قو می رواج کے مطا بق کے ہو تے ہیں لیکن اس جگہ اس کے معنے پسندیدہ اور بہتر کے ہیں.مطلب یہ ہے کہ خوا ہ عدّت کے بعد عورتیں نکا ح کر لیں خواہ اپنے وا لدین یا دوسرے رشتہ داروں کے ہا ں چلی جا ئیں یا کو ئی ملازمت اختیا ر کر لیں تم پر کو ئی اعتراض نہیں.تمہیں اس حکم کی رو سے یہ نہیں چا ہیے کہ انہیں روکو.وَ لِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ١ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ۰۰۲۴۲ اور جن عورتوں کو طلاق دی جائے انہیں بھی (اپنے) حالات کے مطابق کچھ سامان دینا ضروری ہے.یہ بات( ہم نے) متقیوں كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَؒ۰۰۲۴۳ پر واجب کر دی ہے.اسی طرح اللہ (تعالیٰ) اپنے احکام تمہارے (فائدہ کے) لئے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.تفسیر.طلاق کے مضمو ن کوختم کر تے ہو ئے اللہ تعا لیٰ نے مطلّقات سے حسن سلوک کے حکم کو پھر دہرایا ہے.چو نکہ عام طور پر مطلّقات سے نا را ضگی ہو تی ہے اس لئے فر مایا.تمہیں ان سے اچھا سلو ک کر نا چا ہیے اور پچھلی آ یتوں پر اس کا عطف کر کے یہ بھی بتا دیاکہ مطلّقہ عورتوں کو بھی اگر عر صہ عدت سے زیا دہ گھر میں رہنے کی ضرورت ہو تو رہنے دیا جا ئے اور ان کو بھی ان کے منا سب حال فا ئدہ پہنچا نا چا ہیے.یہ متقیوںپر حق قرا ر دیا گیا ہے.پس مطلقہ عورت سے بھی بے مر وتی نہیںکر نی چا ہیے اور اس کو عدّت کے فوراً بعد گھر سے نہیں نکا ل دیناچا ہیے.بلکہ بطریق احسا ن اسے مو قعہ دینا چا ہیے تا کہ وہ اطمینا ن سے نقل مکا نی کا انتظام کرسکے.
Page 391
مسلمانوں پر تعجب ہے کہ اللہ تعا لیٰ تو مطلّقہ عورتوں سے مہر کے علا وہ حسن سلوک کرنے کا بھی ارشاد فر ماتا ہے اور مسلمان عورتوں کے مہر تک بھی کھا جا تے ہیں.اگراس حکم پر عمل کیا جا ئے تو کس قدر فسا د اور جھگڑے دور ہو جائیں.اور طلا ق جو صرف مجبو ری میں حلال ہے اس تلخی کے پیدا کر نے کامو جب نہ ہو جس کا مو جب وہ اب ہو رہی ہے.بلکہ دونو ں فر یق محسوس کر یں کہ مجبو ری سے علیٰحد گی اختیار کی گئی ہے ورنہ آ پس میں کو ئی تلخی یا بد مزگی نہیں ہے.پھر فرمایا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے فائدہ کے لئے اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم خطاؤں اور کمزوریوں سے بچو.اٰیٰۃٌ کے عام معنے علامت کے ہوتے ہیں.لیکن قرآن کریم میں کہیں خدا تعالیٰ نے اپنی طرف توجہ دلانے والی باتوں کو.کہیں ایمان کی طرف راہنمائی کرنے والی باتوں کو.کہیں عذاب سے بچانے والی باتوں کواور کہیں تمدّن کا صحیح راستہ بتانے والی باتوں کو آیات کہا ہے (اقرب).اس جگہ آیات سے وہ احکام مرادہیںجو صحیح تمدن کی طرف راہنمائی کرتے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ شریعت کے بیان کرنے میں یہ امر ہر جگہ مدّنظر رکھا گیاہے.کہ تمام ضروری امور کے متعلق تعلیم آجائے اور ایسے رنگ میں بیان کر دی جائے کہ بنی نوع انسان بدیوں اور کمزوریوں سے بچ جائیںجس پر تَعْقِلُوْنَ کا لفظ دلالت کرتا ہے.اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ کیا تجھے ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو موت سے بچنے کے لئے جبکہ وہ ہزاروں (کی تعداد میں )تھے الْمَوْتِ١۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا١۫ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ اپنے گھروں سے نکلے تھے.اس پر اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ.اس کے بعد اس نے انہیں زندہ کر دیا.لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ۰۰۲۴۴ اللہ لوگوں پر یقیناً (بڑا) فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے.تفسیر.فرماتا ہے کیا تجھے ان لوگوںکی خبر نہیںپہنچی جوموت سے بچنے کے لئے اپنے گھروںسے ایسی حالت میں نکلے تھے جبکہ وہ ہزاروںکی تعداد میں تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم مر جاؤ.چنانچہ اُس موت کے بعداللہ تعالیٰ نے پھرانہیں زندہ کردیا.
Page 392
یہ لوگ کون تھے جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے اور جن کو خداتعالے نے کہا کہ مرجاؤ؟ اور پھر یہ کون لوگ تھے جنہیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیاتِ نوعطافرمائی؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بنی اسرائیل تھے جو موت کے ڈر کی وجہ سے ملک مصرسے نکلے تھے.چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس آیت میں جتنی باتیں بیان کی ہیں وہ سب کی سب بنی اسرائیل کے واقعات میں دکھائی دیتی ہیں.موت کے ڈر کا ذکر اس آیت میںکیا گیاہے کہ وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ۠ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ (البقرۃ: ۵۰) یعنی اس وقت کو یا د کرو جبکہ ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے اس حا لت میں نجا ت دی کہ وہ تمہیں بد تر ین عذاب دے رہی تھی.وہ تمہارے لڑکو ں کو قتل کر دیتی تھی اور تمہا ری عورتوں کو زندہ رکھتی تھی.اور گھروں سے نکلنے کا ذکر اس آ یت میںکیا گیا ہے کہ.وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ(الشعراء: ۵۳) یعنی ہم نے مو سٰی کی طر ف وحی کی کہ میرے بندوں کو را توں رات نکا ل کر لے جا.اور میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ تمہا را پیچھا کیاجائےگا.وَ هُمْ اُلُوْفٌ والی علا مت بھی بنی اسرا ئیل پر ہی چسپا ں ہو تی ہے.کیو نکہ جب وہ مصر سے نکلے تو اس وقت وہ صرف چند ہزار ہی تھے.اس میںکو ئی شبہ نہیں کہ پیدا ئش باب ۴۶آ یت ۲۷ میں لکھا ہے کہ بنی اسرا ئیل جب مصر میں آئے تو صرف ۷۰ تھے لیکن تورات ہمیں یہ بھی بتا تی ہے کہ ۲۱۵ سال کے بعد مو سٰی کے زما نہ میں ان کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ عورتوں اور بچوں کو نکا ل کر وہ چھ لا کھ کے قریب پہنچ گئے.چنا نچہ خروج باب ۱۲ آ یت ۳۷ میں لکھا ہے.’’اور بنی اسرا ئیل نے رعمسیس سے سکا ت تک پیدل سفر کیا.اور با ل بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی چھ لا کھ مر د تھے.‘‘ اسی طر ح گنتی باب ۱آیت ۴۶ میں ان کی تعداد چھ لا کھ تین ہزار پا نچ سو پچا س بتا ئی گئی ہے.اگر مردوں کی تعداد کو ملحوظ رکھ کر عورتوں اور بچوںکو بھی شامل کر لیا جائے تو کل تعداد ۲۵لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے مگر۲۱۵ سال کے عرصہ میںستّرآدمیوں کا ۲۵لاکھ تک پہنچ جانا با لکل عقل کے خلاف بات ہے اورپھر واقعہ کے بھی خلاف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصرسے کنعان کی طرف ہجرت کی تو وہ چالیس سال تک جنگلوں میںرہے توکیا پچیس لاکھ آدمیوںکی روٹی کاانتظام چالیس سال تک ان جنگلوں میں ہو سکتا تھا؟ بے شک بائیبل میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لئے آسمان سے بٹیر اتارے اورزمین میںترنجبین پیدا کر دی(خروج باب ۱۱۶ ٓیت ۱۳ تا ۱۵).لیکن بائیبل کے بیان کے مطابق یہ خوراک سارے عرصہ کےلئے مہیانہیں ہوئی تھی.پھر دوسرے عرصہ میں اتنے آدمیوں کے
Page 393
لئے خوراک کہاں سے لاتے تھے؟ پھر بائیبل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک چشمہ سے پانی بھی پی لیتے تھے.اب کیا کوئی عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک ایک چشمہ سے پچیس لاکھ آدمی سیراب ہو سکتا ہے؟ دراصل اس بیان میں سخت مبالغہ سے کام لیا گیا ہے حقیقت وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل جو فرعون کے ظلم سے ڈر کر بھاگے تھے ان کی تعدادصرف چندہزارتھی.ورنہ پچیس لاکھ یہودی فلسطین کے چھوٹے چھوٹے قبائل سے ڈر کس طرح سکتے تھے؟ فلسطین کی آبادی تو اپنی شان و شوکت کے زمانہ میں بھی ۲۵ - ۳۰ لاکھ سے زیادہ نہیں بڑھی.بلکہ اس زمانہ میں بھی تقسیم سے پہلے اس کی آبادی اٹھارہ لاکھ کے قریب تھی.پرانے زمانہ میں جبکہ خوراک ادھر ادھر پہنچانے کے سامان مفقود تھے غیر زرعی علاقوں میں بڑی آبادی ہو ہی نہیں سکتی تھی.پس موسیٰ ؑ کے وقت میں یقیناً سارے فلسطین کی آبادی چند ہزارافراد پر مشتمل ہو گی.چنانچہ بنی اسرائیل اور ان کے دشمنوں کی لڑائیوں میں ہمیشہ سینکڑوں اور ہزاروں افراد کا ہی پتہ لگتا ہے.اگر موسیٰ ؑ کے ساتھ ۲۵ لاکھ آدمی فلسطین میں آئے تھے تو سفر کا زمانہ تو الگ رہا حکومت کے زمانہ میں بھی ان کی خوراک کا انتظام نہ ہو سکتا تھا اور لڑائی کا تو ذکر ہی کیا ہے یہ لوگ تو اپنے کند ھوں کے دھکوں سے ہی ان چند ہزار افراد سے فلسطین کو خالی کرا سکتے تھے جو ان سے پہلے وہاں بس رہے تھے.پس وَ هُمْ اُلُوْفٌ میں جن لو گوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بنی اسرا ئیل ہی ہیں.(مزید تفصیل کےلئے دیکھیں تفسیر کبیرسورۃ مریم تا انبیاءجلد ۷ تا ۸ ) چو تھی با ت اس آ یت میں یہ بیا ن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم مر جا ؤ.اس امر کا ذکر بھی قرآ ن کر یم نے ایک دوسری جگہ ان الفا ظ میں کیا ہے کہ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً١ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ١ؕ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ(المآ ئدۃ : ۲۷) یعنی جب مو سٰی کی نا فر ما نی کر تے ہو ئے بنی اسرا ئیل نے لڑائی کر نے سے انکا ر کر دیا تواللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ انہیں اب اس ملک سے چا لیس سال کے لئے محروم کر دیا گیا ہے.وہ زمین میں سرگردان پھر تے رہیں گے پس تو با غی لو گو ں پر افسوس نہ کر.پا نچویں با ت یہ بیا ن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے بعد پھر زندہ کر دیا.اسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ان الفا ظ میں بیا ن کیا ہے کہ وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ.ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.(البقرۃ: ۵۶,۵۷) یعنی اس وقت کو بھی یا د کر و جب تم نے کہا تھا کہ اے موسٰی! ہم تیری با ت ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو آ منے سا منے نہ دیکھ لیں.اس پر تمہیں ایک مہلک عذاب نے پکڑ لیا اور تم اپنی آ نکھ سے اپنے فعل کا انجا م دیکھ رہے تھے.پھر ہم نے
Page 394
تمہاری ہلا کت کے بعد تمہیں اس لئے اٹھا یا کہ تم شکر گذار بنو.میرے نزدیک اس آ یت میںنَرَى اللّٰهَ جَهْرَةًسے مراد اُن کا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ( المآ ئد ۃ: ۲۵) والا جملہ ہے.اس کے بعد انہیں چا لیس سال کی سزا ملی.جو صا عقہ تھی.غرض اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ هُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ سے مراد بنی اسرا ئیل ہی ہیں جو فر عون کے متو اتر مظالم کا تختہ مشق بنے ہو ئے تھے اور ہلا کت کے گڑھے میں گر ے ہو ئے تھے.ان کے لڑ کے مارے جا تے تھے اور قومی زندگی با لکل تبا ہ ہو چکی تھی.اللہ تعالیٰ ان کو ملک مصر سے بچا کرلا یا.اور اس نے فلسطین کاان سے وعدہ کیا اور حکم دیاکہ دشمن سے لڑو اور فتح حا صل کر لو.مگر وہ اپنی نا دا نی سے کہہ اُٹھے کہ يٰمُوْسٰۤى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَاۤ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ(المآئدۃ :۲۵) یعنی اے مو سٰی !جب تک وہ لوگ اس میں مو جو د ہیں ہم اُس سرزمین میں کبھی دا خل نہیں ہوںگے.اس لئے تو اور تیرا ربّ دونو ں جا ؤ اور ان سے جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے.اس کا نتیجہ یہ ہو ا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مو ت نا زل کی.یعنی وہ چا لیس سال تک اللہ تعالیٰ کی نا را ضگی کا مورد رہے.اس کے بعد ان کی اگلی نسل جب جوان ہو ئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے منشا کے ما تحت قر با نیوں سے کا م لیا تو خدا تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا.یعنی کنعان کے دروازے ان کے لئے کھل گئے اور حکومت پر انہوں نے قبضہ کر لیا.اسی کی طرف ثُمَّ اَحْیَا ھُمْ میں اشارہ کیا گیا ہے.اور اسی کی طرف ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ میں اشارہ تھا.فَقَالَ لَھُمُ اللّٰہُ مُوْتُوْا میں اس طرف بھی اشا رہ پا یا جا تا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے مو ت کے خوف سے نکلے اور انہوں نے چا ہا کہ وہ زندگی حا صل کریں تو ان کی اس خواہش کوپورا کر نے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو تدبیر بتا ئی وہ یہ تھی کہ تم اپنے لئے مو ت اختیار کر و.ایک ایسی قوم جو مو ت سے بچنے کے لئے گھروں سے نکلی تھی.اسے قدرتی طور پر یہ علاج بہت عجیب نظر آ یا.وہ لو گ جنہوں نے اپنا وطن خواہ وہ اختیار کردہ ہی ہو.املا ک خواہ تھوڑے ہی ہو ں.اپنی عزت یا رتبہ خواہ قلیل ہی ہو.اپنے جلیس اور ہم صحبت دوست اور وہ ملک جس کی وہ زبان سمجھتے تھے صرف اس لئے کہ انہیں زندگی ملے اور وہ مو ت سے بچ سکیں کُلی طور پر چھوڑدیا.وہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے ماتحت ایک ایسے ملک کی طرف چلے گئے جہا ں کی زبان وہ نہیں جانتے تھے جہا ں ان کی کو ئی جا ئیداد نہیں تھی.جہا ں کے لو گ ان کی دیا نت سے اور یہ لو گ ان کی دیا نت سے واقف نہ تھے.جہاں کے لوگوں کی نگا ہ میں ان کے چھوٹے بڑے میں کو ئی تمیز نہ تھی.یہ قربا نی کوئی معمولی قربا نی نہ تھی.یہ قربا نی صرف اس لئے کی گئی تھی کہ انہیں جان
Page 395
بہت پیاری تھی ورنہ وہ اس ملک کو چھوڑتے ہی کیو ں؟مگر جب وہ وہاں پہنچے تو خدا تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا کہ وہ زندگی کہاں ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا؟ اﷲ تعالیٰ نے فرمایا تم موت قبول کرو.پھر زندہ ہو جائو گے.وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کیونکہ جو پیالہ فرعون انہیںپلا رہا تھا وہی اﷲ تعالیٰ نے انہیں دیا فرعون نے فیصلہ کیا تھاکہ وہ مر جائیںمگر انہوں نے کہا ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہم خدا تعالیٰ سے فریاد کریںگے لیکن جب انہوں نے خدا تعالیٰ سے فریاد کی تو وہاں سے بھی ان کو یہی جواب ملا کہ مر جائو.انہیں دونوں جگہوں سے موت ہی کا پیالہ ملا.وہ حیران تھے کہ فرعون کو دوست سمجھیں یا خدا تعالیٰ کو دشمن.فرعون انہیں زندہ کرنا چاہتا تھا یا خدا تعالیٰ انہیں مارنا چاہتا ہے کیونکہ دونوں پیالوں پر موت لکھی ہوئی تھی.وہ گھبرائے.ان میں سے کمزوروں نے کہا کہ ہم تو موت سے بچنے کے لئے آئے تھے اگر یہی پیالہ ہمیں پینا ہوتا تو وہیں کیوں نہ پی لیتے اتنی تکالیف برداشت کرنےکی کیا ضرورت تھی؟ ہم اس پیالہ کو پینے کے لیے تیار نہیں ہم سے دھوکا کیا گیا ہے اگر موت ہی ہمیں ملنی تھی تو کیوں ہم سے زندگی کا وعدہ کیا گیا تھا.اتنی امیدیں دلانےکے بعد ہمیں قوم میں کیوں شرمندہ کرایا؟ وہ ہنسیں گے کہ بیوقوف موت سے بھاگے تھے وہاں بھی موت ہی نصیب ہوئی.وہ اس مشکل کو حل نہ کر سکے سوائے اس کے کہ ان میں سے کمزوروں نے کہا کہ ہم یہ پیالہ پینے کے لئے تیا ر نہیں.عزت کی زندگی جس کا ہم سے وعدہ تھا وہ ہمیں دو.یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی.فرعون انہیںتباہ کرنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارے سب لڑکے مارے جائیں گے اور لازماً لڑکیا ں غیروں سے بیاہی جائیںگی اور تمہاری نسل مٹ جائےگی اورغیروں کی نسل جاری ہوجائےگی.تم اس موت سے بچو اورذلّت کی زندگی برداشت نہ کرو.خدا تعالیٰ نے بتایاہےکہ حیات کا پیالہ تمہارے لئے کنعان کی سرزمین میں تیار ہے چنانچہ انہوں نے گھر بار چھوڑا.مال جو اٹھایا نہ گیاوہیں چھوڑا عزت سے ہاتھ دھوئے.ایک باقاعدہ حکومت کاآرام کھویا.وہ نکلے اور چل پڑے.خدا تعالیٰ فرماتا ہےوَ هُمْ اُلُوْفٌ وہ چند ہزار تھے.جو اپنے گھروںسے نکلے.ان میں بہت سی عورتیں اور بچے بھی ہوںگے.عام طور پر صرف پانچواں حصہ بالغ مرد ہوتے ہیں پھر ان میں کچھ بوڑھے بھی ہوںگے.متمدن اقوام میں چھ فیصدی مرد جنگ کے قابل ہوتے ہیں.اور غیر متمدن قوموںمیںسولہ فیصدی.اگر وہ پچاس ہزار بھی ہوں تو ان میں سے زیادہ سے زیادہ آٹھ ہزار لڑائی کے قابل مرد ہوںگے.اور وہ بھی نا تجربہ کار.پتھیرے بھلا کیا جانے کہ جنگ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا لائو.وہ ملک جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا.اس پر ایک زبردست قوم کے لوگ جن کے چہرے خون سے بھرے ہوئے تھے.جنہیں اگر دائیں طرف عرب کے جنگجوئوں سے مقابلہ کرنا پڑتا
Page 396
تو بائیں طرف یونانیوں سے.تہذیب کے گہوارہ میں پلی ہوئی تین قوموں یونانیوں ، ایرانیوں اور مصریوں سے انہیں واسطہ پڑتا.وہ تینوں کے طریق کار سے واقف تھے وہ خود بھی مہذب اور بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے تھے.اور بنی اسرائیل سے قریباً دس گنا تھے.حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جنگجو اور خونخوار قوم دکھا کر کہا کہ اس قوم کو مار دو پھر حکومت تمہارے ہاتھ آجائےگی.بنی اسرائیل پر حیرت کا اظہار کرنا آسان ہے لیکن ذرا سوچو! تمہارا ایک دوست تمہاری دعوت کرے.وقت مقررہ پر وہ تمہیں بلا کرلے جائے اور جب وہ بازار میں پہنچے تو ایک بڑے ہوٹل میں چلا جائے.جہاں ہر ایک چیز پانچ چھ گنا قیمت پر ملتی ہو اور کہے کہ یہ ہوٹل ہے اس میں آپ آٹھ دس روپے خرچ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں.اور دوسری طرف ایک ایسا مکان بھی ہے جہاں سے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے.آپ اس کے اندر گھس جائیں مالک مکان کا سر لٹھ سے پھوڑ دیں اور کھانا لے لیں اس جواب کو سن کر تمہاری کیا حالت ہوگی؟ تم اس کو ذلیل کرنے والا تمسخر خیال کرو گے اور اس دوست سے ناراض ہو جائو گے.شاید تم میں سے جوشیلے ایسے دوست پر حملہ ہی کر بیٹھیں یہی حالت یہاں ہوئی.سینکڑوں میل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس وعدہ پر کہ وہاں انہیں بادشاہت ملے گی لائے.مگر وہاں پہنچ کر انہیں کہہ دیا کہ کنعان پر قابض قوم کو مار دو.اور ان سے حکومت چھین لو.اس جہالت کو دیکھ کر جو بنی اسرائیل میں اس وقت پھیلی ہوئی تھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس جواب پر سر پیٹ لیا ہو گا.وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوںگے کہ تم نے وعدے کیا کئے تھے اور اب کہہ کیا رہے ہو؟ وہ کہتے ہوںگے کہ وہیںہمیںکیوں نہ کہہ دیا کہ فرعون کا سر اڑا دو.اور اس سے حکومت چھین لو.وہاں پر تو ہم یہ کر بھی سکتے تھے کیونکہ ہمارے آدمی فرعون کے گھروں میں کام کرتے تھے وزراء ہمارے واقف تھے اور کئی سہولتیں ہمیں میسر تھیں.لیکن یہاں پر زبان اور ہے اس لئے ہم جاسوسی بھی تو نہیں کر سکتے.وہ ذرائع ہمیں یہاں میسر نہیں ان لوگوں کو مارنا بھلا کونسا آسان کام تھا کہ تم ہمیں وہاں سے نکال لائے اور یہاں آکر کہہ دیا کہ ان کو مارو.اور ملک پر قبضہ کرلو.یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا لیکن خدا تعالیٰ انہیں نظر نہ آتا تھا.ورنہ وہ اس سے ہی جھگڑا کرتے.حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نظر آتے تھے اس لیے انہی کو وہ مخاطب کرتے تھے اوربظاہر حالات انہوں نے شرافت سے ہی کام لیا.ورنہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہوتے.کہ تم نے ہمارے ساتھ نعوذ باللّٰہ دھوکا کیا ہے.بائیبل میں آتا ہے کہ وہ روئے پیٹے اور بچوں کی طرح روٹھ گئے.(استثنا باب ۱ آیت ۲۶،۲۷) قر آ ن کریم فر ما تا ہے.انہوں نے کہا.اے مو سیٰ علیہ السلام! اِذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ.(المآئدة :۲۵) ہما رے مدِّ مقا بل ایک تجر بہ کار اور جنگجو قوم ہے.ان کے پاس اسلحہ بھی ہم سے زیادہ ہے وہ اپنے
Page 397
وطن میں ہیں اور راستوں سے اچھی طرح وا قف ہیں.ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا تعا قب کیسے کر یں وہ محفوظ قلعوں میںہیں اور ہم جنگلو ں میں.تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں بادشا ہت دو گے اس لئے ہم توہا تھ نہیں اٹھائیں گے اور یہیںبیٹھے رہیں گے.تم اور تمہا را خدا جاؤ اور ملک فتح کر کے ہمیں دے دو.بظا ہر معلو م ہو تا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے انہوں نے لفظاً پو را نہیں کیا.لیکن جب ہم اس وا قعہ کوایک اور نقطہ نگا ہ سے دیکھتے ہیں تو اس کی شکل ہی بدل جا تی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم نے مکہ کی فتح پر انصار سے مخا طب ہوکر فرما یا اے انصار! کیا تم نے یہ کہا ہے کہ خو ن تو ہما ری تلوا روں سے ٹپک رہا ہے اور مالِ غنیمت مہا جر ین میں تقسیم کر دیا گیا ہے.انہوں نے عرض کیا.حضور! ہم میں سے ایک نوجوان نے نا دانی سے ایسا کہہ دیاہے.آ پؐ نے فر ما یا.تم کہہ سکتے ہو کہ محمد(صلی اللہ علیہ و سلم) کو ہم نے بے درپا یا.ہم نے اسے اپنے گھر میںجگہ دی.اُس کے بھا ئی اُس کے خون کے پیا سے تھے.ہم اس کے آ گے پیچھے لڑے.دنیا میں اس کی بات کوئی نہ سنتا تھاہم نے لوگوں تک اس کا پیغا م پہنچا یا.پھر جب فتح ہو ئی تو اس نے مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا اور ہمیں کچھ نہ دیا.لیکن اگر تم چا ہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ محمد(صلی اللہ علیہ و سلم) نے ہمیں قربِ الہٰی حا صل کرا یا.تقویٰ جیسی نعمت دی.خدا تعالیٰ کی محبت دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے فتح دی.اور خدا ئی فوجوں نے مکہ فتح کیا.مکہ اُس کاپیدا ئشی مقا م تھا اور مہا جر ین کا وطن.انہیں تو قع تھی کہ مکہ فتح کرکے وہ اپنے گھروں پر قبضہ کر لیںگے مگر مکہ مکر مہ والے تو چند اونٹ لے گئے اور ہم اپنے سا تھ رسول اللہ کو لے آئے(بخاری کتاب المغازی باب غزوة الطائف فی شوالٍ سنة ثمان).یہی دونو ںرُخ یہا ں ہیں.اگر حکو مت کے رنگ میںکوئی تغیر خدا تعالیٰ کومنظور نہیں تھا اور وہ ایسی ہی حکو مت پسند کر تا جیسی فر عون کی تھی تو فر عون سے حکومت چھین کر بنی اسر ائیل کو کیوں دینا چا ہتا.خدا تعالیٰ تو ایسی قوم کو با دشا ہت دینا چا ہتا تھا جو اخلا ق کی خو شنما حکو مت قا ئم کر تی.خدا تعالیٰ بنی اسر ائیل کو ایسی زندگی نہیں دینا چا ہتا تھاجو ختم ہو جاتی.ایسی زندگی تو چمار بھی دیتا ہے جبکہ وہ بچہ پیدا کرتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ انہیں ایسی زندگی دینا چاہتا تھا جو کو ئی اور نہیں دے سکتا تھا.خدا تعالیٰ انہیں اخلا ق فا ضلہ کی ہمیشہ کی زندگی دینا چا ہتا تھاجوفر عون انہیں نہیں دے سکتا تھا.اور ایسی زندگی بغیر تربیت اور قر با نی کی عا دت کے انہیں نہیں مل سکتی تھی.خدا تعالیٰ انہیں اپنے تا زہ نشا نو ں کے سا تھ زندہ کر نا چا ہتا تھا تا ان میں سے ہر ایک دس دس کے مقا بل میں کھڑا ہو.پھر خدا تعالیٰ ان کو فتح دیتا تو ایک زندہ نشان دیکھتے جس سےان کی اصلا ح ہوتی اور اس طر ح ان کو حقیقی زند گی ملتی گو یا پیا لے دونوں موت کے تھے.لیکن فر عون کے پیا لہ میں شربت بھی مو ت کا تھا اور خدا تعالیٰ کے پیا لہ میں زند گی کا.
Page 398
یہ فر ق تھا جسے وہ سمجھ نہ سکے.اگر وہ فر عون کا پیا لہ پی لیتے تو ہمیشہ کے لئےانہیں موت ملتی.لیکن وہ خدا تعالیٰ کا پیا لہ پی لیتے تو وقتی مو ت ہو تی جس کے بعد ہمیشہ کے لئے انہیں زندگی مل جا تی.مگر انہوں نے اس فر ق کو نہ سمجھا اور خدا تعالیٰ کا پیش کر دہ مو ت کا پیا لہ پینے سے بھی اسی طر ح انکا ر کر دیا جس طرح فر عون کا پیا لہ پینے سے انکا ر کیا تھا.تب خدا تعالیٰ نے انہیں فر ما یا مُوْ تُوْ ا تم اپنے ہا تھ سے مو ت لینے سے انکا ر کرتے ہو.اب ہم خود تمہیں مو ت دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فر عو ن کی دی ہو ئی مو ت اور اپنی دی ہو ئی مو ت میں فر ق رکھا.وہ لو گ گھر سے تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر اعتبار کر کے ہی نکلے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ عر صہ کی موت کے بعد انہیں پھر زندگی دے دی اور اس طر ح اس وعدہ کو پورا کر دیا.یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے قومی جدوجہد کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے.دعا ئے ابرا ہیمی میں رسول کر یم صلی اللہ علیہ و سلم کے چا ر کا م بتا ئے گئے تھے.يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ(البقرۃ:۱۳۰) اوّل آ یا ت الٰہی سنانے کاکام.دوم تعلیم کتاب کاکام.سو م تعلیم حکمت کاکام.چہارم تزکیہ نفوس کاکام.یہ آ یت يُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ کے ما تحت ہے.یہا ں قومو ں کی تر قی کے ذرائع بیا ن کئے گئے ہیں.اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ مثا ل دے کر بتا یا ہے کہ قو میں کس طر ح تر قی کیاکرتی ہیں.جب بھی کسی قوم کو مو ت کا ڈر ہو تو اس کا یہی علا ج ہے کہ یا تو وہ اپنے ہا تھ سے مو ت قبول کر ے یا خدا تعالیٰ کے ہا تھ سے مو ت قبول کر ے.اپنے ہاتھ سے موت قبول کرنے میں کئی آسانیاں ہوتی ہیں.حضرت مسیح موعودعلیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم اپنے ہاتھ سے ابتلاء لو تو تم اسے کم کر سکتے ہو.جیسے سردی میں وضو کے لئے پانی کی ٹھنڈک کو تم دورکر سکتے ہو.اسی طرح جنگ میں تم بخوشی موت قبول کرتے ہو لیکن تم اس سے بچائو کے لئے تلوار ہاتھ میں پکڑ لیتے ہو اور بدن پر زرہ پہن لیتے ہو تاکہ جہاں تک ہو سکے موت کے اثر کو کم کر دو.اگر تم زخمی ہو تو علاج کر اسکتے ہو لیکن خدا تعالیٰ کی دی ہوئی موت سے تم کوئی بچائو نہیں کر سکتے خدا تعالیٰ کا قانون کام کرتا چلا جاتا ہے.اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس طرح تکلیف کم ہو گی یا زیادہ مثلاً ہیضہ یا طاعون کی وبائیں بلا لحاظ مارتی چلی جاتی ہیں لیکن تم خود ایک چیز کی تکلیف کو کم کر سکتے ہو.مثلاً کانٹا چبھ جائے تو تم اسے اپنے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو.کیونکہ دوسرے سے تمہیں یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ اس تکلیف کو کم کرنے کی ویسی ہی کوشش کرے گا جیسی تم کر سکتے ہو.پس جب قوم کی موت آتی ہے.تو اس کا علاج زندہ رہنا نہیں بلکہ موت قبول کرنا ہوتا ہے.دنیا میں تین قسم کی قومیں ہوتی ہیں ایک تووہ جو موت کو خود قبول کر لیتی ہیں.اور بعد میں انہیں ہمیشہ کے لئے
Page 399
زندگی مل جاتی ہے.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھی تھے.صحابہ ؓ کے سامنے موت پیش ہوئی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا.جس کے نتیجہ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی.جنگ بدر کے موقعہ پر تمام صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ نہیں گئے تھے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے بعض مصالح کی بناء پر انہیں جنگ کی خبر نہیں دی تھی گو آپ کو اس کا علم تھا.مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کا ارادہ فرمایا.تو آپؐ نے انصار اورمہاجرین کو جمع کیا.اور فرمایا.اے لوگو! مجھے مشورہ دو کہ اب کیا کرنا چاہیے اس پر مہاجرین کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یارسول صلی اللہ! مشورہ کا کیا سوال ہے؟ ہم لڑنے کے لئے حاضر ہیں مگر جب کوئی مہاجر بیٹھ جاتا آپ پھر فرماتے کہ اے لوگو! مجھے مشورہ دو.جب آپؐ نے بار بار یہ الفاظ دہرائے.تو انصار سمجھ گئے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے.چنانچہ ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوںنے عرض کیاکہ یارسول اللہ! آ پؐ کی مرا دشاید ہم انصارسے ہے.آ پؐ نے فر ما یا.ہا ں.اُس نے کہا.یا رسول اللہ! شا ید آ پ کا اشارہ اُس معا ہدہ کی طر ف ہے جو ہجر ت کے وقت ہم نے آ پ سے کیا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر تو ہم دشمن کا مقابلہ کریںگے مگر مد ینہ سے با ہر آ پ کی حفا ظت کے ذمہ دار نہیں ہوںگے.آ پؐ نے فرمایا.تم ٹھیک سمجھے میرا اشارہ اسی طرف ہے.اس نے کہا یا رسول اللہ! بیشک ہما را یہ معا ہدہ تھا کہ ہم مد ینہ سے باہر نہیں لڑ یں گے.لیکن یا رسول اللہ! وہ ابتدائی زما نہ تھا.اب خدا کا نورہم نے خود اترتے دیکھ لیا ہے.اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آ پ میدا نِ جنگ میں جا ئیں اور ہم نہ جائیں.ہم ان انصار کی طرف سے بھی جو علم نہ ہو نے کی وجہ سے مدینہ میں رہ گئے ہیں حضور کو یقین دلا تے ہیںکہ اگر وہ بھی یہا ں مو جو د ہو تے تو ضرور آ پ کے سا تھ جنگ میں شا مل ہو تے پھر اُس نے کہا.یا رسول اللہ! اب معاہدات کاکیا سو ال ہے؟آ پ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں گھو ڑے ڈال دو تو ہم سمندر میں گھو ڑے ڈا لنے کےلئے بھی تیار ہیں اور اگر لڑائی ہو ئی تو یا رسول اللہ ہم آ پ کے دا ئیں بھی لڑیں گے اور با ئیں بھی لڑیں گے اور آ گے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور کو ئی شخص آ پ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری لاشوں کو روندتا ہوا نہ گزرے.یہ فقرہ صحا بہ ؓ کو اس قدر پسند تھا کہ ایک صحا بی جو چو دہ یا اٹھا رہ جنگوں میںشریک ہو ئے کہا کر تے تھےکہ با وجو د اس کے کہ مجھے اتنی جنگوں میں شمو لیت کا فخر حا صل ہے میرے نز دیک اُس صحا بی کا یہ فقرہ میری سار ی لڑائیوں سے بہتر تھا.کاش یہ میرے منہ سے نکلتا.(بخاری کتاب المغازی باب قصّۃ غزوۃ بدر) غر ض ایک تو یہ قوم تھی جنہو ں نے بخو شی موت کو قبول کیا اور اس کے مطا بق اس سے سلو ک ہوا.دو سری قوم حضرت موسٰی کی تھی.اللہ تعالیٰ نے اس سے زندگی کا وعدہ کیا اور اس نے وعدہ کے ایفاء کا لفظاً مطا لبہ کیا انہوں نے کہا
Page 400
تم ہم کو زندگی دینے کے وعدہ پر لائے تھے.تم نے ہمیں با دشا ہت دینے کا وعدہ کیا تھا تم وہ ملک لے کر ہمیں دے دو.ہم لڑ کر ملک لینے کے لئے تیا ر نہیں.اس پر خدا تعالیٰ نے انہیں مو ت دےدی اور چالیس سال تک اس ملک سے محروم کر دیا مگر چو نکہ زندگی کا وعدہ بھی تھا اس لئے پھر زندگی بھی دےدی.لیکن اس وقت جب کہ وہ نسل جس نے خود موت لینے سے انکا ر کر دیا تھا بیا با نوں میں ہلا ک ہو چکی تھی.خدا تعالیٰ نے اِنَّا ھٰھُنَا قٰعِدُوْنَ کہنے والوںکے بچوں کو جنہوں نے یہ فقرہ نہیں کہا تھا.اٹھا یا اور زندگی کا وعدہ ان کے زما نہ میں پورا کر دیا.چنا نچہ ثُمَّ اَحْیَاھُمْ میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے.تیسری قسم کی قوم وہ ہو تی ہے جس سے کو ئی وعدہ نہیں ہو تا.یہ قوم جب مو ت کے مونہہ میں آ تی ہے تو اس سے سلوک اس کی اپنی ہمّت کے مطا بق ہو تا ہے کبھی اپنی کو شش سے ایسی قوم بچ جا تی ہے اور کبھی ہلاک ہو جاتی ہے.غرض اس آ یت میںاللہ تعالیٰ نے یہ ایک عجیب نکتہ بتا یا ہے کہ غلا م قوم اور مغلو ب لوگ کبھی زندگی نہیں پا سکتے جب تک کہ پہلے اپنے لئے مو ت کو اختیار نہ کر لیں.وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ میں بھی یہ بتا یا کہ خدا تعالیٰ جو مجا ہدات بتا تا ہے وہ قومی ترقی کے لئے ضروری ہو تے ہیں مگر لو گ ان پر شور مچا دیتے ہیں کہ ہم مر گئے.بو جھو ں میں دب گئے حا لا نکہ فا ئدہ ان کااپنا ہوتاہے.وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۰۰۲۴۵ اور تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو.اور جان لو کہ اللہ بہت سننے والا (اور )جاننے والا ہے.تفسیر.فر ما تا ہے.اے امّت محمدیہ تم اُ س قو م کی حا لت کو دیکھو جسے مو سیٰ علیہ السلام مصر سے اس لئے نکال کر لائے تھے کہ اسے ایک ملک کی حکومت حا صل ہو.لیکن جب انہیں اپنے دشمنوں سے جو اُ ن کے ملک پر قابض تھے لڑنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے انکا ر کر دیا.اس پر خدا تعالیٰ نے انہیں اس ملک کی حکو مت سے چالیس سا ل تک کے لئے محروم کر دیا اور وہ جنگلو ںمیں بھٹک بھٹک کر مر گئے.غرض با وجو د اس کے کہ مو ت ان کو اپنے گھروں میں بھی آ نی تھی انہوں نے خداتعا لیٰ کی راہ میں موت کا پیا لہ پینے سے انکا ر کر دیا اور تبا ہ ہو گئے.خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ تمہیں اس قوم کے حا لات سے عبرت حا صل کر نی چا ہیے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جہا د کر نے سے کبھی انکار نہیں کر نا چاہیے.جو قوم موت سے ڈرتی ہے وہ دنیا میں کبھی زندہ نہیں رہ سکتی کیو نکہ مو ت سے ڈرنا ہی اُسے موت
Page 401
کا شکار بنا دیتا ہے.وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ میںبتا یاکہ بے شک تم کمزور اور بے سروسا مان ہو.اور تمہارا دشمن بڑا تجر بہ کار اور سارے سا ما ن سے مسلح ہے مگراللہ تعالیٰ سمیع ہے وہ تمہاری دعا ؤں کو سنے گا.اور وہ علیم ہے یعنی ان مشکلا ت کو بھی جا نتا ہے جو تمہیں پیش آ ئیں گی.اس لئے تم اس پر بھروسہ رکھو وہ تمہار ی دعا ؤں کو سنےگا اور تمہیں دشمن کے مقا بلہ میں کامیا بی و کامرا نی عطا فرمائےگا.مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ کیا کوئی ہے جو اللہ کو( اپنے مال کا )ایک اچھا ٹکڑا کاٹ کر دے تاکہ وہ اسے اس کے لئے بہت بہت بڑھائے.اور اَضْعَافًا كَثِيْرَةً١ؕ وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُۜطُ١۪ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ۰۰۲۴۶ اللہ (کی یہ بھی سنت ہے کہ وہ بندہ کا مال) لیتا ہے اور بڑھاتا ہے.اور آخر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا.حلّ لُغات.یُقْرضُ اَقْرَضَ سے مضارع وا حد مذکر غا ئب کا صیغہ ہے اور اس کے معنے قرض دینے کے بھی ہیں اور کاٹ کر الگ کر دینے کے بھی چنا نچہ اَقْرَضَہٗ کے یہ بھی معنے ہیںکہ قَطَعَ لَہٗ قِطْعَۃً اُس کے لئے ایک ٹکڑہ کا ٹ کر الگ کر دیا.اور یہ بھی کہ اَعْطَا ہُ قَرْ ضًا اُسے قرض دیا.(اقرب) لسا ن العرب میں لکھا ہے.اَلْقَرْضُ اَلْقَطْعُ وَ ھُوَ مَا اَسْلَفَہٗ مِنْ اِحْسَا نٍ اَوْمِنْ اَسَاءَ ۃٍ یعنی ہر وہ عمل جسے انسا ن اپنے آ گے بھیجے خواہ وہ نیک ہو یا بد اُسے قرض کہتے ہیں.یہ ضروری نہیں کہ اس سے مراد مال ہی ہو.چنانچہ اُمیّہ کا شعر ہے؎ کُلُّ امْرِيٍ سَوْفَ یُجْزٰی قَرْضَہٗ حَسَنًا اَوْسَیِّئًا مَدِ یْنًا مِثْلَ مَا دَانَ یعنی ہر شخص کو اس کے قرض کا بدلہ ملے گا خواہ وہ اچھا ہویا برا اور وہ اپنے کئے کی جزاء پا ئےگا.اَلْقَرْضُ کُلُّ اَمْرٍیُتَجَا زٰی بِہٖ مِنَ النَّاسِ.ہر ایسا فعل جس کا انسا ن کو بدلہ دیا جائے قرض کہلاتا ہے قَرَضْتُہٗکے معنے ہیںجَا زَیْتُہٗ میں نے اُسے بدلہ دیا.تَقُوْ لُ الْعَرَبُ لَکَ عِنْدِیْ قَرَضٌ حَسَنٌ وَ قَرَضٌ سَیِّیءٌ.عرب کہتے ہیں کہ تیرا میرے ساتھ اچھا معا ملہ ہے، میں نے اس کا بدلہ دینا ہے.اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں
Page 402
کہ تیرا معا ملہ میرے ساتھ برُا ہے میںنے اس کا بدلہ دینا ہے.وَاَصْلُ الْقَرْضِ مَایُعْطِیْہِ الرَّ جُلُ اَوْ یَفْعَلُہٗ لِیُجَا زٰی عَلَیْہِ وَاللّٰہُ لَا یَسْتَقْرِضُ مِنْ عِوَضٍ وَلٰکِنَّہٗ یَبْلُوْ عِبَا دَہٗ.اصل قرض یہ ہے کہ انسان کسی کو کوئی چیز دے یا ایسا کام کرے جس کا اُسے بدلہ دیا جا ئے.کہتے ہیں خدا تعالیٰ عوض کے بدلہ میں نہیں لیتا بلکہ وہ اپنے بندوں کی آ زما ئش کر تا ہے.لبید کہتا ہے؎ وَاِذَا جُوْ زِیْتَ قَرْضًا فَاَ جْزِہٖ اِنَّمَا یُجْزَی الْفَتٰی لَیْسَ الْجَمَلٗ کہ جب تجھے قر ض دیا جا ئے تو تُو اس کا بدلہ دے.کیو نکہ بہا در آ دمی ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.اونٹ نہیں دیا کرتے.یعنی تُو ایسا نہ بن کہ لو گ تجھ سے معا ملہ کر یں تو تُو اُن سے اچھا معا ملہ نہ کرے.اِ سی طرح کہتے ہیں اَلْقَرْضُ فِیْ قَوْلِہٖ تَعَالٰی مَنْ یُّقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا اِسْمٌ لَیْسَ بِمَصْدَرٍ وَلَوْ کَانَ مَصْدَرًا لَکَانَ اِقْرَاضًا وَلٰکِنَّ الْقَرْضَ کُلُّ مَایُلْتَمَسُ عَلَیْہِ الْجَزَآءُ کہ قر ض کا لفظ اِس آ یت میں اسم ہے نہ کہ مصدر.اگر مصدرہو تا تو اِقْرَاض ہو نا چا ہیے تھا.مگر یہا ں قَرْض ہے.جس کے معنے ہیں ہر وہ چیز جس پر انسان بدلہ چا ہے.اخفش کہتا ہے یُقْرِضُ اللّٰہَ یَفْعَلُ فِعْلًا حَسَنًا فِیْ اِتِّبَاعِ اَمْرِہٖ یُقَالُ لِکُلِّ مَنْ فَعَلَ اِلَیْہِ خَیْرًا لَقَدْ اَحْسَنْتَ قَرْضِیْ کہ یہ محا ورہ ہے کہ جس آ دمی سے اچھا سلوک کیا جا ئے.وہ کہتا ہے تو نے مجھے اچھا قر ض دیاہے یعنی اچھا معا ملہ کیا ہے یا یوں کہتے ہیں کہ لَقَدْ اَقْرَ ضْتَنِیْ قَرْ ضًا حَسَنًا اَیْ اَدَّیْتَ اِلَيَّ خَیْرًا تو نے مجھے قرضہ حسنہ دیا ہے.یعنی میرے سا تھ بڑی نیکی کی ہے.ان معنوں کی رُو سے زیر تفسیر آ یت کا مفہوم یہ ہو گا کہ (۱) کون ہے جواللہ تعالیٰ کے احکا م کی اطا عت کرے ایسی صورت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اُس کی جزاء کی اُ مید رکھے.(۲) کون ہے جو اپنے ما ل کا ایک حصہ کا ٹ کراللہ تعالیٰ کی راہ میں دے.گو یا دونوں معنوں کی رو سے غرض یہ ہو گی کہ خدا تعالیٰ کی اتباع کر ے اور اپنے ما ل کا ایک حصہ کا ٹ کر اس کی راہ میں خر چ کرے.اَضْعَا فٌ ضِعْفٌ کی جمع ہے.اور ضِعْفٌ کے معنے عربی زبا ن میں کئی ہیں.(۱)محض بڑھا دینا.(۲) جتنی چیز ہو اتنی ہی اور بڑ ھا دینا یعنی دوگنا کر دینا.(۳) کہتے ہیں کہ یہ کم از کم افزائش ہے بڑی حد مقرر نہیں کی جا سکتی خوا ہ اُسے کروڑ گنا بڑھا دیا جا ئے(اقرب).کروڑ گنا بھی اضعاف میں داخل ہے.یہ جملہ ہے تو سوا لیہ مگر تحریص کا فا ئدہ دیتا ہے.اس کی اصل عبا رت یوں ہو گی اَیُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا فَیُضَا عِفَہٗ لَہٗ یا ھَلْ مِنْ
Page 403
مُّقْرِضٍ فَیُضَاعِفَہٗ.تفسیر.جیسا کہ حل لغا ت میں بتا یا جا چکا ہے اس آ یت کے معنے یہ ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کا ایک عمدہ حصہ کاٹ کراللہ تعالیٰ کو دےدے تا کہ وہ اُسے خو د دینے والے کے فا ئدہ کے لئے بڑھائے اور اُسے ترقی دیتا چلا جا ئے اس آ یت میں نہایت لطیف پیرا یہ میں مو منوں کوخدا تعالیٰ کے لئے اپنے اموا ل خرچ کر نے کی نصیحت کی گئی ہے اور بتا یا گیاہے کہ اوّل تو ہم تم سے سا را ما ل نہیں ما نگتے بلکہ ما ل کا صرف ایک حصہ ما نگتے ہیں اور پھر ما نگتے بھی اس لئے ہیں کہ تم ایک روپیہ دو تو تمہیں اس کا دس گنا اجر دیا جا ئے.خدا تعالیٰ کی محبت اور اُس کی رضا حاصل کرنے کا اس سے زیا دہ سہل اور آ سان طریق اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی یاد رکھنا چا ہیے کہ انسا ن جب خدا تعالیٰ کے لئے اپنا ما ل خرچ کر ے تو اسے تین با تیں خا ص طور پر ملحوظ رکھنی چا ہئیں.او ّ ل.اُس کے دل میں صدقہ و خیرات کرتے وقت کوئی انقباض پیدا نہ ہو.بلکہ وہ پوری بشاشت اور خوش دلی کے سا تھ اُس میں حصہ لے.دوم.جسے کو ئی چیز دی جا ئے اُس پر احسا ن نہ جتا یا جا ئے اور نہ اس کے نتیجہ میں اس پر کو ئی نا وا جب بو جھ ڈالا جا ئے بلکہ یہ سمجھا جا ئے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس نیکی کی تو فیق دے کر در حقیقت مجھ پر احسا ن کیاہے.سوم.جو چیز دی جا ئے وہ اپنے مال کا بہترین حصہ ہو.یہ تینوں امور مندرجہ ذیل آ یتوں سے مستنبط ہو تے ہیں.اللہ تعالیٰ منا فقوں کے متعلق فر ماتا ہے وَلَا یُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَھُمْ کَا رِھُوْنَ(التوبۃ:۵۴) وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں کرا ہت اور نا پسند ید گی کے سا تھ اپنے ما ل خرچ کر تے ہیں.اسی طرح فرما تاہے اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَھُمْ فِيْ سَبِیْلِ اللّٰہِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَا اَنْفَقُوْامَنًّا وَّلَا اَذَیً(البقرۃ:۲۶۳) مومن وہ ہیں جو اپنے ما لوں کواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر نے کے بعد نہ تو کسی رنگ میں دوسروں پراحسان جتلا تے ہیں اور نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں.پھر فر ما تا ہے لَنْ تَنَا لُوْ االْبِرَّ حَتّٰی تُنْفِقُوْ امِمَّا تُحِبُّوْنَ.(اٰل عمران: ۹۳) تم کا مل نیکی کا مقام ہر گز نہیںپا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسند یدہ اشیا ء میں سے خرچ نہ کرو.پس مَنْ ذَاالَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًاحَسَنًا کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے مال کا اچھے سے اچھا ٹکڑا الگ کر کےا للہ تعالیٰ کی راہ میں دے جس کے دیتے وقت نہ تو اس کے دل میں انقبا ض پیدا ہو اور نہ اس کے بعد وہ دوسروں پر احسا ن جتلا ئے یا ان کے لئے کسی قسم کی تکلیف کا مو جب بنے.اور یقیناً یاد رکھو کہ جو لوگ ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں اس نیکی کا بہتر سے بہتر اجر عنا یت فر مائےگا اور ان کا ایک ایک عمل ان کے لئے ہزاروں
Page 404
گنا برکا ت کا مو جب ہو گا.مَنْ ذَاالَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًاحَسَنًا بظاہر تو ایک سوال ہے مگر اس کی غرض لوگوں کو تحر یص و تر غیب دلا نا ہے اور مطلب یہ ہے کہ کیاکو ئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے را ستہ میں اپنا مال خرچ کر ے اور خدا تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے اور اسے اپنے قرب میں جگہ دے؟ اِس آ یت کے ایک یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو قرض حسنہ دیا کرو.یعنی اس کے بندوں سے حسن سلوک کرو اور جو غریب ہیں ان کی مدد کرو.کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے نہیں دینا بندوں ہی کو دینا ہوتا ہے.بعض دفعہ بندوں کو دینے کا نام بھی خدا تعالیٰ کو دینا رکھا جاتا ہے.جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ بعض لوگوں سے کہے گا کہ اے ابن آدم! میںبیمار ہوا لیکن تو نے میری عیادت نہ کی.میں بھوکا رہا اور میں نے کھانا بھی مانگا مگر تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا.میں پیا سا رہا اور تجھ سے پانی بھی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہ پلایا.اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ بندہ خدا تعالیٰ سے پوچھے گا کہ اے اللہ! تو کب بیمار ہوا؟ کہ میں نے تیری عیادت نہ کی.تو نے کب مجھ سے پانی مانگا؟ کہ میں نے تجھے پانی نہ پلایا.تو نے کب مجھ سے کھانا مانگا؟ کہ میں نے تجھے نہ کھلایا.اس پر خدا تعالیٰ فرمائےگا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا مگر تو نے اس کی بیمار پرسی نہ کی.میرے فلاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے اسے کھانا نہ کھلایا.میرے فلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہ پلایا.(مسلم کتاب البرّ والصّلۃ والآداب باب فی فضل عیادۃ المریض) پس خدا تعالیٰ کو قرض دینے کا ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ اس کے بندوں سے نیک سلوک کیا جائے اور ان کی مالی پریشانیوں کو دور کرنے میں حصہ لیا جائے.عیسائیوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے حالانکہ اس حدیث کے الفاظ بعینہٖ انجیل میں بھی آئے ہیں.وہاں لکھا ہے.’’ تب بادشاہ انہیں جو اس کے داہنے ہیں کہے گا.اے میرے باپ کے مبارک لوگو! اس بادشاہت کو جو دنیا کی بنیاد ڈالنے سے تمہارے لئے تیار کی گئی میراث میں لو کیونکہ میں بھوکا تھا.تم نے مجھے کھانا کھلایا.میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا.میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا.میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا.بیمار تھا تم نے میری عیادت کی.قید میں تھا تم میرے پاس آئے.اس وقت راست باز اسے جواب میں کہیں گے.اے خداوند کب ہم نے تجھے بھوکادیکھا اور کھانا کھلایا.پیاسا دیکھا اور پانی پلایا.کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور اپنے گھر میں اتارا یا ننگا دیکھا اور
Page 405
کپڑا پہنایا.ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تجھ پاس آئے.تب بادشاہ ان سے جواب میں کہے گا.میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ کیا تومیرے ساتھ کیا.تب وہ بائیں طرف والوں سے بھی یہی کہے گا.اے ملعونو! میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میںجائو.جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی.کیونکہ میںبھوکا تھا پر تم نے کھانے کو نہ دیا.پیاساتھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا.پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھرمیں نہ اتارا.ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا.بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی.تب وے بھی اسے جواب میں کہیں گے.اے خدا وند کب ہم نے تجھے بھوکا یا پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی.تب وہ انہیں جواب میں کہے گا.میں تم سے سچ کہتا ہوں.کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے ساتھ نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا." (متی باب ۲۵ آیت ۳۴تا۴۰) انجیل کے اس حوالہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندوں کو دینا خدا تعالیٰ کو دینا کہلاتا ہے.پس مَنْ ذَاالَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰہَ سے مَنْ ذَاالَّذِیْ یُقْرِضُ عِبَادَ اللّٰہِ مراد ہے.گویا یہاں ایک مضاف محذوف ہے جو عِبَادَ اللہِ ہے اور چونکہ اس سے پہلے وَقَاتِلُوْافِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے.اس لئے اس کے معنے یہ ہیں کہ لڑائیوں کے ایام میں بعض کو مالی نقصان پہنچیں گے.تم کو چاہیے کہ انہیں قرض دےکر ان کے حالات درست کرو.یہ قرض گویا تم خدا تعالیٰ کو دو گے.اور یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لئے ایک دانہ بھی خرچ کرتا ہے.خدا تعالیٰ اسے بڑھاتا ہے اور اتنا بڑھاتا ہے کہ کسی کو اس کی امید بھی نہیں ہوتی.حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو.انہوںنے اپنا ایک بیٹا خدا تعالیٰ کے لئے قربان کیا اور خدا تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلہ میں اتنی اولاد دینے کا وعدہ دیا جس کا آسمان کے ستاروں کی طرح شمار ہی نہیں ہو سکتا(پیدائش باب ۱۳ آیت ۱۵ تا ۱۷).اسی طرح حضرت اسمعٰیل علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے لئے ایک بے آب و گیاہ جنگل میںرہنا منظور کیا.جس کے بدلہ میں ان کو یہ مرتبہ ملا کہ اوّلین و آخرین کے سردارحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ان کی نسل میں سے پیدا ہوئے.پس فرماتا ہے کہ تم یہ مت گمان کرو کہ تمہاری قربانیاں ضائع چلی جائیں گی.خدا تعالیٰ نےاس کے بدلہ میں تمہارے لئے جو انعام مقرر کیا ہے وہ تمہارے وہم و گمان سے بھی بالا ہے.فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً پر بعض لوگوں نے اعتراض کیاہے کہ اَضْعَا فًا کس طر ح آسکتا ہے.یہا ں تو
Page 406
ضِعَافًا آنا چا ہیے تھا(تفسیر مظہری زیر آیت ھذا).اس کا بعض نے یہ جواب دیاہے کہ چو نکہ تعددّ انوا ع کی طرف اشارہ کر نا مدّنظر تھا.اس لئے اَضْعَافًا رکھا گیا ہے، ضِعَا فًاسے تو صرف یہی مرا د ہو سکتا تھا کہ وہ اُسے کئی گنُے بڑھائےگا.مگر اَضْعَا فًامیں اس با ت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بڑھائےگا بھی اور یہ زیادتی کئی قسم کی ہو گی.پس تعداد انواع کے اظہار کے لئے ضِعَافًا کی بجا ئے اَضْعَا فًا جمع لا ئی گئی ہے.وَ اللّٰهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُۜطُ میں ایک تو اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح تمہارے دوسرے بھائیوں پر مصیبت آ ئی ہے اسی طرح تم پر بھی آ سکتی ہے.کیو نکہ تنگی اور کشائش کے دور بدلتے رہتے ہیں اس لئے ان کی مدد کرنا تمہارا اوّلین فرض ہے.دوسرے اللہ تعالیٰ نے ان الفا ظ میں پہلے جملہ کی مزید تشریح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کےقرض لینے کا کیا مطلب ہے.فر ما یا.اللہ تعالیٰ کی یہ سنّت ہے کہ وہ پہلے اپنے بندوںکا مال لیتا ہے اور پھر اُس کو بڑھا تا اور ترقی دیتا ہے.پس جب تک بندہ قربا نی نہ کر ے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا وہ خا ص فضل بھی نا زل نہیں ہوتا جس کی طرف يَبْصُۜطُکا لفظ اشارہ کر رہا ہے.یَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ تنگی بھی لاتا ہے اور کشائش بھی پیدا کر تا ہے اور جب دونوں اس کے اختیار میں ہیں تو پھر جو بھی اس کے احکا م پر چلے گا اُس کے لئے وہ بسط پیدا کر ےگا اور جو اس کی نافرمانی کر ے گا اس کےلئے وہ قبض یعنی عذاب کی صورت پیدا کر دےگا.اسی طرح اس کے ایک یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی دو ہی حالتیں ہو تی ہیں یا تو قبض کی حا لت ہوتی ہے یا بسط کی.چنانچہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحا بیؓ حا ضر ہوئے.اور انہوں نے کہا.یا رسول اللہ! میں تو منافق ہوں.رسول کر یم صلی اللہ علیہ و سلم نے فر مایا.تم تو مومن ہو تم اپنے آ پ کو منا فق کیوںسمجھتے ہو؟ اس صحا بی ؓ نے کہا یا رسول اللہ ! میں جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھارہتا ہوں یوں معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت میرے سا منے ہیں.اور خشیت الٰہی کا زور ہو تا ہے لیکن جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو وہ حالت قائم نہیں رہتی.رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فر مایا.یہی توخالص ایمان ہے.پھر آ پؐ نے فرمایا.اگر انسا ن ایک ہی حالت پر رہے تو وہ مر نہ جائے.غرض قبض و بسط دونوں حالتیں انسا ن پر آ تی رہتی ہیں اگر انسا ن کی ہر وقت ایک قسم کی حالت رہے تو اگر جسما نی طور پر نہیں تو دماغی طور پر وہ یقینًا مرجائےگا اور پا گل ہو جائےگا.مجنونوں اور عقل مندوں میں یہی فر ق ہوتا ہے کہ مجنو ن پر ایک ہی حالت ہمیشہ طاری رہتی ہے.اور عقلمندوں پر اتار چڑھا ؤ آ تا رہتا ہے.مجنون ایک ہی قسم کے خیا لات میں مبتلا رہتا ہے لیکن عقل مند شخص کے خیا لات ایک قسم کے نہیں رہتے.غرض قبض وبسط
Page 407
کی حالتیں انسا ن کے ساتھ لا زم کر دی گئی ہیں کبھی اس کے اندر بسط کی لہر پیدا ہوتی ہے اور وہ دین کے لئے سب کچھ قربان کر نے کے لئے تیار ہو جاتا ہے.اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حساب کر نے بیٹھ جاتا ہے کہ میں کتنی قربا نی کر سکتا ہوں.یہ حسا ب کر نےوالی حالت قبض کی حالت ہو تی ہے اور جب کو ئی شخص سب کچھ دینے کے لئے تیار ہو جا تا ہے اور اس میں خوشی محسوس کرتا ہے تو وہ بسط کی حا لت ہوتی ہے.پس فرمایا کہ تم دونوں حا لتوں میں خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرو.کیو نکہ تنگی بھی عا رضی چیز ہے اور فراخی بھی عا رضی.اور چو نکہ سوال ہو سکتا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ کے پاس ہما را مال بڑھتا رہتا ہے تو اس کا ہمیں کیا فا ئدہ ؟ اس لئے فر ما یا کہ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.اصل گھر توتمہارا وہی ہے.پس جو کچھ تم ہما رے پاس بھیجتے ہو ہم اسے بڑھا تے رہتے ہیں.جب تم آ ؤ گے تو خدا تعالیٰ نے تمہارا مال بہت بڑھا رکھا ہو گا.اور وہ تمہیںمل جائےگا.جیسے کو ئی ملا زم با ہر جاتا ہے تو روپیہ اپنے گھر بھیجتا رہتا ہے اور اس کی بیوی اسے جمع کر تی رہتی ہے.مگر خدا تعالیٰ صرف جمع ہی نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھا تا بھی رہتا ہے.پس اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَمیں بتا یا کہ آ خر ایک دن تم نے خدا کی طرف لوٹنا ہے.جہاں ایک دائمی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے.پس عا رضی چیزوںکی وجہ سے اپنی دائمی زندگی کو نقصان مت پہنچاؤ اور جس قدر بھی نیکی میں حصہ لے سکتے ہو لو.قرآن کر یم کا کمال دیکھو کہ اس میںا نفس اور اموال کی تر تیب کیسے عجیب طور پر رکھی گئی ہے.چو نکہ جنگ میںسب سے پہلے سپا ہی کاوجو د ضروری ہو تا ہے جو قوم اور ملّت کے لئے اپنی جا ن کی با زی لگا دیتا ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ کا حکم دے کر مومنوں سے ان کی جان کا مطا لبہ کیا.اس کے بعد دوسرا سوال خزانہ کی مضبوطی کا ہو تا ہے کیو نکہ جب کوئی قوم میدانِ جہا د میں نکلتی ہے تو ملک کے خزانہ پر جنگی اخراجات کا غیر معمولی بار پڑ جاتا ہے اور اس کمی کو پورا کر نا ضروری ہوتا ہے ورنہ جنگ زیا دہ دیر تک نہیں لڑی جا سکتی.اسی حکمت کے ما تحت اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر مالی قربانیوں کی تحریک فر مادی اور اس طرح قومی اور مذہبی استحکام کے لئے جان اور مال کی قر با نیوں کو ایک بنیادی حیثیت دے کر ان کی طبعی تر تیب بھی قا ئم کر دی کہ پہلا درجہ جا نی قربانیوں کا ہے اور دوسرا درجہ مالی قربانیوں کا.
Page 408
اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى١ۘ کیا تجھے بنی اسرائیل کے ان سر کردہ لوگوں کا حال نہیں معلوم ہوا.جو موسیٰ کے بعدگزرے ہیں.اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے کوئی (شخص) بادشاہ (بنا کر )کھڑا کیجئیے تاکہ ہم (اس کے ماتحت ہو کر ) اللّٰهِ١ؕ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا اللہ کی راہ میں جنگ کریں.اس نے کہا (کہیں )ایسا تو نہیں ہو گا کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم جنگ نہ کرو.تُقَاتِلُوْا١ؕ قَالُوْا وَ مَا لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَدْ انہوں نے کہا( ایسا نہیں ہو گا )اور ہمیں کیاہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں گے حالانکہ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَآىِٕنَا١ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اپنے بچوں سے( جدا کیا گیا ہے) مگر جب ان پر جنگ فرض کی گئی الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ۰۰۲۴۷ تو ان میں سے ایک قلیل (سی) جماعت کے سوا (باقی) سب پھر گئے.اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے.حل لغات.مَلَأٌ اس کے اصل معنے بھر دینے کے ہیں.کہتے ہیں.مَلَأَ الْاِ نَاءَ بِا لْمَاءِ اُس نے بر تن کو پا نی سے بھر دیا.مُلِئَی رُعْبًا اُس کا دل خوف سے بھر گیا.اَلْمَلَأُ کے معنے ہیں.سرداران قوم.بڑے آ دمی.کیونکہ جب مجلس میں بڑا آ دمی آجاتا ہے تو کہتے ہیں.اب مجلس بھر گئی ہے.اب کسی کی ضرورت نہیں رہی.غرباء خواہ پچا س بیٹھے ہو ئے ہوں جب تک بڑا آ دمی نہ آ جائے تب تک یہی کہتے ہیں کہ ابھی رونق نہیں ہوئی.اور اس وقت تک کام بھی شروع نہیںکر تے جب تک کہ وہ آ نہ جائے.اس لئے مَلَأٌ بڑے لوگوں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے وجود سے لوگوں کی مجلس کوبھر دیتے ہیں.اسی طرح ان کے خوف یا محبت کی وجہ سے بھی لوگوں کے دل بھرے ہو ئے ہوتے ہیں.(اقرب)
Page 409
ھَلْ عَسَیْتُمْ عَسٰی بعض جگہ تو امکان کےلئے آتا ہے اور بعض جگہ تو قع کے لئے جب یہ لفظ خدا تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو امکان کی طرف اشارہ ہو تا ہے یعنی اس امر کو بعید مت سمجھو.(مفردات) مَا لَنَا یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے.تفسیر.گذشتہ آ یا ت میںاللہ تعالیٰ نے بنی اسرا ئیل کا ایک واقعہ بیا ن کر کے مسلما نو ں کونصیحت کی تھی کہ تم خدا کے لئے موت قبول کر نے سے کبھی انکا ر نہ کرنا اب ایک اور واقعہ بیا ن فر ماتا ہے جو بنی اسرائیل کے سرداروں کے سا تھ تعلق رکھتا ہے کہ انہوں نے دشمن سے لڑائی کر نے کے لئے ایک با دشاہ بنا ئے جا نے کی اپنے نبی کے سا منے درخواست پیش کی اور کہا کہ دشمن کی طرف سے ہم پر متواتر ظلم کیاجا رہا ہے ہمیں اپنے مکا نوں اور جا ئیدادوں سے بے دخل کیا گیا ہے اور ہمیں اپنے بچوں سے بھی جُدا کر دیا گیا ہے.اب ہم پر ایک با دشاہ مقرر کیاجا ئے تا کہ ہم خدا تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کریں.یہاں مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى کے الفا ظ سے فوراً بعد مراد نہیں کیو نکہ فوراً بعد حضرت یوشع ؑ ہو ئے تھے جو نبی بھی تھے اور با دشاہ بھی (یشوع باب ۱ آیت ا تا ۴).اور یہ واقعہ جیسا کہ آ گے چل کر بیا ن کیا جائےگا کئی سو سال بعد ہوا.ھَلْ عَسَیْتُمْ میں اس نبی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی گئی تو تم انکار کر دو.چنانچہ اس نے کہا کہ تم پہلے اپنے دلوں کو ٹٹول لو ایسا نہ ہو کہ لڑائی فر ض کی جائے اور تم انکارکرکے گناہ گار بنو.وَ قَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَآىِٕنَاکے یہ معنیٰ ہیں کہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکالاگیا اور اپنے بیٹوں سے بھی جدا کیاگیا.یعنی ہما ری زمینوں اور مکا نا ت پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور ہما رے بیٹے بھی قتل کئے گئے یا مکا نا ت کے ساتھ بیٹے بھی انہوں نے چھین لئے.اور جب ہم نےاللہ تعالیٰ کے راستہ میں اس قدر تکالیف برداشت کی ہیں تو اب ہم لڑائی کر نے سے کیوں انکار کر یںگے؟ اِ ن الفا ظ سے صاف معلوم ہو تا ہے کہ یہ کسی بعد کے زما نہ کی بات ہے.ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زما نہ میں تو بنی اسرائیل کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ ! تُو اور تیرا ربّ دونوں جا ؤ اور دشمنوں سے لڑتے پھرو.ہم تو یہیں بیٹھے ہیں.لیکن اس مو قعہ پر انہوں نے یہ جواب نہیں دیا.بلکہ کہا کہ ہم جہاد میں کیوں حصہ نہیں لیں گے جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے بھی نکا لا گیا اور اپنے بچوں سے بھی علیٰحدہ کیا گیا.اس میںکوئی شبہ نہیں کہ جب لڑائی کا وقت آ یاتو جیسا کہ اگلی آ یات سے واضح ہے ان میںسے بہت سے لوگ متزلزل ہو گئے.مگر بہر حال انہوں نے شروع میں لڑنے
Page 410
سے انکار نہیں کیا.بلکہ خود خواہش کی کہ ہم پر کو ئی با دشاہ مقرر کیاجائے تا کہ دشمن کے مظالم کا انسداد ہو.یہ بات بتاتی ہے کہ ان آ یات میںجس واقعہ کا ذکر ہے وہ حضرت مو سیٰ علیہ السلام کے زما نہ سے بہت بعد کا ہے.ورنہ حضرت موسیٰ ؑ کے زما نہ میں تو انہوں نے لڑنے سے کلّی طور پر انکار کردیا تھا مگر یہاں انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم پر کو ئی بادشاہ مقرر کیا جا ئے تا کہ ہم خدا تعالیٰ کے راستہ میں اپنے دشمنوں سے لڑائی کر یں.وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لئے طالوت (یعنی جدعون ) کو بادشاہ بنا کر (اس کام کے لئے ) مَلِكًا١ؕ قَالُوْۤا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ اَحَقُّ کھڑا کیا ہے.انہوں نے کہا.اسے ہم پر حکومت کس طرح مل سکتی ہے جبکہ ہم اس کی نسبت حکومت کے زیادہ حق دار ہیں.بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ١ؕ قَالَ اِنَّ اور اسے مالی فراخی بھی (کوئی ایسی زیادہ) عطا نہیں ہوئی.اس نےکہا کہ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ اللہ نے اسے تم پر یقیناًفضیلت دی ہے اور اسے علمی اور جسمانی لحاظ سے (تم سے زیادہ) فراخی عطا کی ہے.الْجِسْمِ١ؕ وَ اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ١ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۰۰۲۴۸ اور اللہ جسے پسند کر تا ہے اسے اپنا ملک عطا کرتا ہے.اور اللہ کشائش دینے والا (اور )بہت جاننے والا ہے.تفسیر.بنی اسرا ئیل نے جب درخواست کی کہ ہمارے لئے ایک با دشاہ مقرر کیا جائے جس کی کما ن میں ہم دشمنوں سے جنگ کریں تو ان کا خیال تھا کہ انہی میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کردیا جا ئےگا.لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتا تھا اس لئے ان کی منشاء کے خلاف ایک شخص کو با دشاہ مقرر کر دیا.اِس پر اُن کی مخفی ایمانی کمزوری ظاہر ہو گئی اور انہوں نے اعتراض کر نے شروع کر دئیے کہ اسے کیوں بادشاہ بنا دیا گیا ہے ؟اور پھر انہوں نے اپنے اس اعتراض کو تقویت دینے کے لئے کہا.(۱) ہمارے مقا بلہ میں اسے کوئی ظاہری وجاہت حاصل
Page 411
نہیں.ہم اعلیٰ خا ندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ادنیٰ خا ندان میں سے ہے اس لئے بادشاہت ہمارا حق تھا نہ کہ اس کا.(۲) یہ ما لی لحاظ سے غربت میں مبتلا ہے حا لا نکہ با دشاہت کے لئے دولت کی ضرورت ہو تی ہے.پس ہم اسے بادشاہ تسلیم کر نے کے لئے تیار نہیں.قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ.اُن کے نبی نے پہلی بات کا تو یہ جواب دیا کہ اس کے انتخاب میں خدائی ہا تھ ہے اور بڑائی اِسی طرح ظاہرہو تی ہے.کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کو دوسروں کے مقا بلہ میںچن لیتا ہے اور پھر اُسے مخالفت کے با وجود کامیاب کر دیتا ہے.اِسی طرح طالوت کو خدا تعالیٰ نے تم میں سے چن لیا ہے اور اس طرح اسے بزرگی اور برتری حاصل ہو گئی ہے.دوسرا سوال اُن کا یہ تھا کہ وہ مال دارنہیں اس کے جواب میں بتا یا کہ زَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ خدا تعالیٰ نے اسے علمی لحاظ سے بہت فراخی عطا فر ما ئی ہے.علم کے لفظ سے اس طرف اشارہ فر ما یاکہ دنیا میں مال علم کے ذریعہ ہی کما یا جا تا ہے اور علم اسے تم سے بہت زیا دہ حاصل ہے ورنہ بیو قوف آ دمی تو اپنے با پ دادا کی کما ئی کو بھی تبا ہ کر دیتا ہے.پس خدا تعالیٰ نے اسے جو علم بخشا ہے اس کے ذریعہ وہ بہت کچھ مال کما لےگا.اسی طرح اس کی علمی بر تری کا ذکر کر کے اس طرف بھی اشارہ فر ما یا کہ صرف دولت کی وجہ سے کو ئی حکومت کا اہل نہیں ہو سکتا.بلکہ اس کے لئے تنظیمی صلا حیتوں کی بھی ضرورت ہو تی ہے اور حکومتی اوصاف کا بھی پا یا جا نا ضروری ہو تا ہے.اور یہ تمام با تیں اسے تم سے زیادہ حا صل ہیں.اسے حکومت کر نے کا ڈھب بھی آ تا ہے اور سیاسیات سے بھی خوب واقف ہے.اس لئے صرف مالی کمزوری دیکھ کر اعتراض نہ کرو.اس کے اندر جو مخفی جو ہر ہیں وہ اپنے وقت پر ظاہر ہوںگے.پھر جسم کے لحاظ سے بتا یا کہ تم لڑائی کر نا چا ہتے تھے.اس کا جسم بھی خوب مضبوط ہے اور اس کی جسما نی طاقتیں اعلیٰ درجہ کی ہیں.اس میں ہمت اور استقلال اور ثبات اور شجا عت کا مادہ پا یا جاتا ہے.پس اس سے زیا دہ اور کون موزون ہو سکتا ہے.یہ مراد نہیں کہ وہ موٹا تازہ ہے.بلکہ مراد یہ ہے کہ مضبوط اور دلیر ہے اور اس میں قوت برداشت اور قر بانی کا مادہ زیادہ پا یا جاتا ہے.چنا نچہ لوگ کہا کر تے ہیں.اَلْمَرْءُ بِاَ صْغَرَ یْہِ بِقَلْبِہٖ وَلِسَا نِہٖ (اقرب).یعنی انسان کی تمام طاقت اُس کی دو چھوٹی سی چیزوں پر موقوف ہے ایک دل پر اور ایک اُس کی زبان پر.اور یہی سچے خلفاء کی علامت ہو تی ہے.حضرت عمررضی اللہ عنہ جب خلیفہ نہ تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہسے کہنے لگے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو جا نے دیں.اس وقت ان سے جنگ کر نا مسلما نوں کےلئے کمزوری کا با عث ہو گا(بخاری کتاب الزکٰوة باب وجوب الزکٰوة).مگر جب اپنی خلا فت کا زما نہ آیا تو کتنے بڑے بڑے کام کئے.دراصل ہمت و استقلال
Page 412
اور استقامت ایک بہت بڑا نشان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے خلفاء کو عطا کیا جاتا ہے.وَ اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُمیں بتا یا کہ اگر تمہارے سوال صحیح بھی مان لئے جائیں تو بھی تمہارا کو ئی حق نہیں کہ اعتراض کر و کیو نکہ فیصلہ ہمیشہ ما لک ہی کیا کر تا ہے اور جب ملک خدا کا ہے تو وہ جسے چاہے دے اس میں کسی کو چون وچرا کی کیا مجال ہے؟جب ہم مالک کی اجا زت سے ملک اس کے سپر د کر تے ہیں تو پھر تم کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ دنیا میں یہ تسلیم شدہ اصل ہے کہ اگر کسی چیز کی ملکیت کے بارہ میں اختلاف ہو جا ئے تو اس با رہ میں اصل مالک کی طرف رجوع کیا جاتا ہے.پس جب خدا نے اُسے اِس غرض کے لئے منتخب فر ما لیا ہے اور اصل حکومت خدا تعالیٰ ہی کی ہے تو تمہارا کیاحق ہے کہ تم اعتراضات کرو؟اِن الفا ظ سے متر شح ہو تا ہے کہ انہوں نے پھر کوئی سوال کر نا تھا کہ اچھااگر اسے علم دیا گیا ہے تو وہ کو نسا علم ہے یا کو نسی استقامت ہے جو اس نے دکھا ئی.اس لئے پہلے ہی اس کا جواب دےدیا کہ وَ اللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ.یعنی آ راء میں تو ہمیشہ اختلاف ہو تا ہے مگر جو مالک ہو اس کی رائے مقدم سمجھی جاتی ہے.پھر خدا تعالیٰ تمہاری رائے کے پیچھے کیوں چلے؟ خصوصاً جبکہ وہ واسع اور علیم ہے.اس میں بتا یا کہ اگر تم مال کے متعلق کہو کہ اس کے پاس نہیں تو ہم واسع ہیں ہم اسے وسعت دے دیںگے.اگر کہو کہ یہ حکومت کرنے کا اہل نہیں تو ہم خوب جا نتے ہیں کہ با دشاہت کا اہل کو ن ہے؟پس اگر تم نے لڑنا ہی ہے تو جاؤ خدا سے لڑو.خدا کا ملک تھا اُس نے جسے چاہا دے دیا.اِس آیت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم سے پہلے آ نے والے انبیاء چونکہ کا مل شریعت لے کر نہیں آ ئے تھے اس لئے جب اصلاح خلق کےلئے الہا م کی ضرورت ہو تی تھی تو کسی نبی کو کھڑا کر دیا جا تا تھا.اور اُسے نبوت کا مقام براہ راست حا صل ہو تا تھا.اور جب نظام میں خلل واقع ہو تا تو کسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا.گویا چونکہ لوگوں کو ابھی اس قدر ذہنی ارتقاء حاصل نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کے لئے جدو جہد کر سکتے اس لئے نہ صرف انبیاء کواللہ تعالیٰ براہ راست مقام نبوت عطا فر ما تا بلکہ ملوک بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر کئے جا تے تھے.جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے وہ انتخا بی نہیں ہوتے تھے بلکہ یا تو ورثہ کے طور پر وہ حکومت حا صل کر تے تھے.یا نبی انہیں خدا تعالیٰ کے حکم کے ما تحت با دشاہ مقرر کر دیتے.مگر رسول کر یم صلی اللہ علیہ و سلم چونکہ ایک کامل تعلیم لےکر آئے تھے اور آ پ کی قوم زیادہ اعلیٰ درجہ کی تھی اس لئے آ پ کے بعد مستقل انبیاء کی ضرورت نہ رہی اور اس کے ساتھ ہی ملوکیت کی ادنیٰ صورت کو بھی اُڑا دیا گیا.اور اس کی ایک کا مل صورت پیدا کر دی گئی.اور انتخاب کو پہلی شرط قرار دیا گیا.اس طرح قومی حقوق کو محفوظ کیا گیاجو پہلے با دشاہوںکی صورت میں محفوظ نہ تھا.
Page 413
وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖۤ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ اور ان کے نبی نے ان سے کہا.کہ اس کی حکومت کی دلیل یہ( بھی) ہے کہ تمہیں التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ (ایک) تابوت ملے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین (ہوگی )اور اس چیز کا بقیہ ہوگا جو موسیٰ کے متعلقین مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ١ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اور ہارون کے متعلقین نے (اپنے پیچھے) چھوڑا.فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہو ں گے.اگر تم مومن ہو تو اس لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْمُّؤْمِنِيْنَؒ۰۰۲۴۹ (بات) میں تمہارے لئے یقیناً ایک (بڑا) نشان ہے.حل لغات.بَقِیَّۃٌ یہ لفظ ایسی چیز پر بولا جاتا ہے جو اعلیٰ درجہ کی ہو.چنا نچہ جب کہیں فُلاَنٌ بَقِیَّۃُ قَوْمِہٖ تو اس کے معنے ہو تے ہیں ھُوَ مِنْ خِیَارِھِمْ.وہ قوم کے شرفاء اور اچھے لو گوں میں سے ہے.(اقرب) قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اِن معنوں میں استعمال ہوا ہے چنا نچہ فر ماتا ہے.وَالْبٰقِیٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابًا وَّ خَیْرٌمَّرَدًّا (مریم: ۷۷) یعنی اچھے اور نیک اعمال خدا تعالیٰ کے حضور ثواب حا صل کر نے کے لحاظ سے بھی اور انجا م کے لحا ظ سے بھی سب سے بہتر شے ہیں.قر آن کریم میں یہ لفظ عقل پر بھی بو لا گیا ہے جیسے آ تا ہے.فَلَوْ لَا کَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِکُمْ اُو لُوْ ا بَقِیَّۃٍ یَّنْھَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِی الْاَرْضِ( ھود: ۱۱۷) یعنی کیوں ان قوموں میں سے جوتم سے پہلے زما نہ میں تھیں ایسے عقل مند لوگ نہ نکلے جو لو گوں کو ملک میں بگاڑ پیدا کر نے سے روکتے.چو نکہ عقل بھی خیر ہی کے معنے رکھتی ہے اور انسان کے لئے مفید ہو تی ہے اور وہ اس کے ذریعہ سے با قی رہتا ہے.اس لئے اُسے بھی بقیہ کہتے ہیں.تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ.تر کہ سے مراد عام طور پر ورثہ ہو تا ہے لیکن تر کہ سے مراد دوسروں کی اعلیٰ صفا ت کا حا مل ہو نا بھی ہو تا ہے.جیسا کہ قرآن کریم میںآتا ہے.یَرِ ثُنِیْ وَ یَرِ ثُ مِنْ اٰلِ یَعْقَوْ بَ ( مریم: ۷) یعنی اےخدا! مجھے اپنے پاس سے وارث دے جو میرا بھی وارث ہو اور سارے بنی اسرائیل کا بھی.سارے
Page 414
بنی اسرائیل کا وارث تو وہ ظاہری طورپر نہیں ہو سکتا تھا.پس مراد یہی ہے کہ اٰلِ یعقوب کی جو نیکیاں ہیں وہ اس میںبھی پیدا ہوں اور وہ ان کا وارث ہو.اس لحاظ سے اس آ یت کے معنے یہ ہو ںگے کہ جو نیک دستور پہلے لو گ چھوڑ گئے ہیں اُن کا وارث ہو.تَحْمِلُہٗ حَمَلَہٗ عَلٰی کَذَا کے معنے ہیں اَغْرَاہُ اُسے کسی کا م پر اکسا یا.اِسی طرح اس کے معنے اٹھا نے کے بھی ہیں.(لسان) تفسیر.گذشتہ آ یا ت میں اس زمانہ کے نبی نےطا لوت پر اعتراض کر نے والوں کو یہ جواب دیا تھا کہ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَ زَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ.یعنی مخفی طا قتوں کواللہ تعالیٰ ہی جا نتا ہے.اور جب اس نے طا لوت کو چنا ہے تو یقیناً وہ تم سے افضل ہے.دوسرے دولت کے زور سے با دشاہت نہیں ہو تی بلکہ علم اور قربانی کی طا قت سے ہوتی ہے.سوان دونوں باتوں میں وہ تم سے بڑھا ہوا ہے.وہ تم سے زیادہ علوم جا نتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے جسم کو انتہا ئی ابتلا ؤں میں ڈالنے کے لئے تیار ہے.اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کے نبی نے انہیں کہاکہ اس انتخاب کے منجا نب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں ایک ایسا تا بوت ملے گا جس میں تمہارے ربّ کی طرف سے سکینت ہو گی اور اس چیز کا بقیہ ہوگا جسے مو سٰی اور ہارون ؑ کی آ ل نے اپنے پیچھے چھوڑا.اور فر شتے اُسے اُٹھا ئے ہو ئے ہوںگے.مفسّرین نے تا بوت سے مراد بنی اسرائیل کا وہ خاص صندوق لیا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تورات کا اصل نسخہ اور موسیٰ ؑ اور ہارون ؑ کے تبّر کات محفوظ تھے.اور بنی اسرائیل سفر و حضر میں اُسے اپنے سا تھ رکھتے تھے.کیو نکہ وہ اُسے بڑا متبرک سمجھتے تھے(الجواہر فی تفسیر القرآن زیر آیت ھٰذا).بائیبل میں بھی اس تا بوت کا ان الفاظ میں ذکر آ تاہے.’’ وے شطیم کی لکڑی کا ایک صندوق بنا ویں جس کی لمبا ئی اڑھا ئی ہا تھ اور چوڑائی ڈیڑ ھ ہاتھ اور اونچا ئی ڈیڑھ ہا تھ ہو وے.‘‘ (خروج باب ۲۵ آیت ۱۰) مگر تعجب ہے قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اس تا بوت کو فر شتے اٹھا ئے ہوئے ہو ںگے مگر بائیبل بتا تی ہے کہ ایک دفعہ دشمن نے ایسا حملہ کیاکہ وہ یہ تابوت بھی اٹھا کر لے گئے.چنانچہ لکھا ہے.’’اور جب لوگ لشکر گاہ میں پھر آئے تھے تب اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ خداوند نے ہم کو فلستیوں کے سا منے کیوں شکست دی.آ ؤ ہم خدا کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے
Page 415
آ ئیں تا کہ وہ ہمارے درمیان ہو کے ہم کو ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں سے رہا ئی دیوے.سو انہوں نے سیلا میں لو گ بھیجے تا کہ وہ ربُّ الا فواج کے عہد کے صندوق کو جو کر وبیوں کے درمیا ن دھرارہتا ہے وہاں سے لے آویں اور عیلی کے دونوں بیٹے حُفنیؔ اور فینحاںؔ خدا کے عہد کے صندوق پا س وہاں حاضر تھے.اور جب خدا وند کے عہد کا صندوق لشکر گاہ میں آ پہنچا.تو اسرائیلی خوب للکارے.ایسا کہ زمین لرز گئی اور فلستیوں نے جو للکارنے کی آ واز سنی تو بو لے کہ ان عبرا نیوں کی لشکر گاہ میں کیسی للکارنے کی آ واز ہے.پھر انہوں نے معلوم کر لیا کہ خدا وند کا صندوق لشکر گاہ میں آ پہنچا.سو فلستی ڈر گئے کہ انہوں نے کہا.خدا لشکر گاہ میں آ یا ہے.اور بولے ہم پر وا ویلا ہے اس لئے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہ ہوا.ہم پر واویلا ہے.ایسے خدا ئے قادر کے ہاتھ سے ہمیں کون بچائےگا.یہ وہ خدا ہے جس نے مصریوں کو میدان میں ہر ایک قسم کی بلا سے مارا.اے فلستیو! تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو.تا کہ تم عبرانیوں کے بندے نہ بنو جیسے کہ وے تمہارے بندے بنے بلکہ مرد کی طرح بہادری کرو اور لڑو.سو فلستی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے اپنے خیمے کو بھا گا.اور وہاں نہا یت بڑی خونر یزی ہوئی کہ تیس ہزار اسرائیلی پیا دے مارے پڑے.اور خدا کا صندوق لُو ٹا گیا.‘‘ ( ا.سموئیل باب ۴آیت ۳ تا ۱۱) سو اگر تو یہاں تا بوت سے مراد وہی تا بوت ہو تو وہ ان کے لئے کسی خوشی کا موجب نہیں ہو سکتا تھا.اور نہ ہی اس سے ان کو کوئی تسلّی ہو سکتی تھی کیو نکہ اس کی مو جو دگی میں وہ شکست کھا چکے تھےحا لا نکہ اس سے پہلے ان کو تا بوت پر اس قدر یقین تھا کہ جب ان کے سب سے بڑے کا ہن کو معلوم ہوا کہ تا بوت دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے تو وہ گر پڑا اور وہیں مر گیا.لیکن قرآن کر یم نے جس تا بوت کا ذکر کیاہے اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ ان کے لئے تسکین کا مو جب ہو گا.پس یہ تا بوت وہ نہیں ہو سکتا.بلکہ اس تا بوت سے یقیناً کچھ اور مراد ہے اس غرض کے لئے جب ہم لغت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو تا ہے کہ تا بوت کے عام معنے تو صندوق کے اور کشتی کے ہو تے ہیں(تاج العروس) لیکن استعارۃً اُسے دل کے معنے میں بھی استعمال کیاجاتا ہے.جس کی تائید اس امر سے ہو تی ہے کہ عربی زبان میں انسانی قلب کو بَیْتُ الْحِکْمَۃِ اور وِعَاءُ الْحِکْمَۃِ اور صَنْدُوْقُ الْحِکْمَۃِ کہنے کے علا وہ تَا بُوْتُ الْحِکْمَۃِ بھی کہتے ہیں(مفردات راغب) اسی طرح لسان العرب کا یہ حوالہ بھی اس کی تا ئید کر تا ہے کہ مَا اَوْدَعْتُ شَیْئًا تَا بُوْتِیْ فَقَدْ تُہٗ مَیں نے اپنے تا بوت یعنی دل میںکوئی ایسی بات نہیں رکھی کہ بعد میں اسے گم کر دیا ہو.یعنی مَیں مستقل مزاج
Page 416
ہوں.جو بات دل میں بیٹھ گئی سو بیٹھ گئی.نیز تا ج العروس میں لکھا ہے.اَلتَّا بُوْتُ اَلْاَ ضْلَاعُ وَ مَا تَحْوِیْہِ کَالْقَلْبِ وَالْکَبِدِ وَغَیْرِ ھِمَا تَشْبِیْھًا بِا لصَّنْدُوْقِ الَّذِیْ یُحْرَزُ فِیْہِ الْمَتَا عُ.یعنی تا بوت کے معنے پسلیوں والے حصہ جسم کے ہیں جس میں دل اور جگر وغیرہ اعضاء ہیں.اور اس حصہ جسم کو تا بوت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی صندوق کی طرح ہو تا ہے جس میں سا مان محفوظ رکھا جاتا ہے.اور کسی علمی یا ایما نی یا راز کی بات کو تا بوت میں رکھنے کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ گو یا وہ سینہ میں لکھی گئی ہے.اور ایسی محفوظ ہو گئی ہے جیسے کوئی چیز صندوق میں رکھ دی جائے.وَ فِیْ اَحْکَامِ الْاَسَاسِ اَلتَّا بُوْتُ: اَلْقَلْبُ اور کتاب احکام الاساس میں بھی تا بوت کے معنے دل کے لکھے ہیں اسی طرح مفردات میں لکھا ہے.قِیْلَ عِبَارَۃٌ عَنِ الْقَلْبِ وَالسَّکِیْنَۃِ وَعَمَّا فِیْہِ مِنَ الْعِلْمِ.یعنی کبھی لفظ تا بوت کو استعارۃً دل کے معنیٰ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے الفاظ قر آ نیہ صاف دلا لت کر رہے ہیں کہ اس جگہ تا بوت سے مراد دل ہے.کیو نکہ فر ماتا ہے اس تا بوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے.اب یہ ظا ہر ہے کہ سکینت دل میں ہوتی ہے نہ کہ صندوقوں میں.اسی طرح اس تابوت کے متعلق فرماتا ہےتَحْمِلُهُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ.فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے.اگر تابوت سے ظاہری صندوق مرا دلیا جا ئے تو یہ قرآنی تعلیم کے خلاف ہو گا کیو نکہ اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے کہ وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا.قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنَ۠ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا.( بنی اسرا ئیل: ۹۵.۹۶) یعنی مخالفین کو ہدا یت الٰہی پر ایما ن لا نے سے صرف یہ بات روکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر رسول کیو ں بھیجا ہے؟ تو کہہ کہ اگر زمین میں فرشتے امن سے چلتے پھرتے تو ہم فر شتوں کو رسول بنا کر بھیجا کر تے.اس آ یت سے ظاہر ہے کہ ملا ئکہ اس طرح لو گوں میں چلتے پھر تے نہیں ہیں جس طرح انسا ن چلتے پھر تے ہیں.پس چو نکہ ظاہری تا بوت کی صورت میں ما ننا پڑتا ہے کہ فر شتے اُسے اُ ٹھا کر ساتھ سا تھ لئے پھر تے تھے اور یہ قر آ نی تعلیم کے خلا ف ہے.اس لئے تابوت سے مراد اس جگہ د ل ہی ہیں.جنہیں فرشتے اٹھا تے تھے اور ہمت بڑھا تے تھے کیو نکہ حَمَلَہٗ عَلٰی کَذَا کے معنے اَغْرَاہُ کے ہیں یعنی اکسا نا اور جوش دلا نا(اقرب) پس معنے یہ ہو ئے کہ اَتَباع طا لو ت کو فر شتے قر بانیوں پر آما دہ کریں گے اور ان کی نصرت ہر شخص کے سا تھ ہو گی.چنا نچہ مورخین کا اِس بات پر اتفاق ہے کہ طا لوت کا لشکر بہت ہی کم تھا اور ایسے قلیل التعداد لشکر کا کثیر افواج پر غا لب آ نا سوا ئے خاص نصرت الٰہی اور ملا ئکہ کی تا ئید کے نا ممکن تھا.(التفسیر الطبری زیر آیت ھٰذا) ضمنی طور پر اس آ یت سے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ ملا ئکہ سے فیوض حا صل کرنے کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ
Page 417
اللہ تعالیٰ کے قا ئم کر دہ خلفا ء سے مخلصا نہ تعلق قا ئم رکھا جا ئے اور ان کی اطا عت کی جا ئے.چنا نچہ اس جگہ طا لوت کے انتخاب میں خدا ئی ہا تھ کا ثبوت یہی پیش کیا گیا ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ کی طر ف سے نئے دل ملیں گے جن میں سکینت کا نز ول ہو گااور خدا تعالیٰ کے ملا ئکہ ان دلوں کو اٹھائے ہو ئےہو ںگے.گو یا طا لوت کے سا تھ تعلق پیدا کرنے کے نتیجہ میں تم میں ایک تغیر عظیم واقع ہو جائے گا تمہاری ہمتیںبلند ہو جا ئیںگی.تمہارے ایمان اور یقین میں اضا فہ ہو جا ئےگا.ملا ئکہ تمہاری تا ئید کے لئے کھڑے ہوجا ئیں گے اور تمہارے دلوں میں استقا مت اور قر با نی کی روح پھو نکتے رہیں گے.پس سچے خلفاء سے تعلق رکھنا ملا ئکہ سے تعلق پیدا کر دیتا اور انسا ن کو انوار الٰہیہ کا مہبط بنا دیتا ہے.اب بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ کا حل کر نا با قی رہ گیا.سو یا د رکھنا چاہیے کہ بَقِیَّۃٌ کے معنے جیسا کہ حل لغات میں بتا یا جا چکا ہے اعلیٰ شے کے ہوتے ہیں.پس بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ سے مراد وہ اخلا ق فا ضلہ ہیں جو حضرت موسیٰ ؑاور حضرت ہا رون ؑ کے متبعین اور آ پ کے مقربین سے ظاہر ہو تے تھے.اور آ یت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے دل ان خو بیوں کے وارث ہوںگے جو آ لِ موسیٰ ؑ اور آل ہا رونؑ نے چھوڑیں ہیں.یہ ویسا ہی فقرہ ہے جیسے حضرت زکریا ؑنےدُعا کر تے ہوئے کہا تھاکہ الٰہی مجھے ایک ایسا لڑکا عطا فرما یَرِ ثُنِیْ وَ یَرِثُ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ(مریم: ۷) جو میرا اور آلِ یعقوب کا وارث ہو.اور مطلب یہ تھا کہ ان کے اخلا ق حسنہ اور خوبیوں کا وارث ہو نہ یہ کہ اُن کی جا ئیداد کا وارث ہو کیو نکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وفات پا ئے قر یباً ایک سو پشت گزر چکی تھی.غرض بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَ اٰلُ هٰرُوْنَ سے یہ مراد ہے کہ طا لو ت کے سا تھیوں میں وہی اخلاق فاضلہ اللہ تعا لیٰ پیدا کر دے گا جو آل مو سیٰ ؑ اور آ ل ہا رون ؑ میں تھے.آ ل مو سٰی و اٰل ہا رون سے یہ مراد نہیں کہ ان دونوں کی الگ الگ اُمتیں تھیں.یہ بات تو با لبداہت باطل ہے ایک قوم میں اور ایک وقت میں اور ایک شریعت پر عمل کر نے والی دو اُمتیں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ اس کا مطلب اہل یعنی اقارب سے ہے اور مراد یہ ہے کہ ان دونوں نبیوں کی اولادوں میں جو خو بیاں تھیں وہ ان میں بھی آ جائیں گی.اگر کہو کہ اہل میں خو بی ہو نا ضروری نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بَقِیَّۃٌ کے لفظ نے بتا دیا ہے کہ اس جگہ خو بیاں مراد ہیں.دوسرے با ئیبل کی کتا ب خروج باب ۴۰ آ یت ۱۲ تا۱۵ سے معلوم ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہارون کو مقدس لباس پہنا یا جائے اور نہ صرف اس کی عزت افزائی کی جائے بلکہ اس کی تمام اولاد کی عزت کر نا بھی بنی اسرائیل پر فرض قرار دیا جا ئے.اور عبا دت گا ہوں کا انتظام ان کے سپر د کیا
Page 418
جائے.چنا نچہ لکھا ہے.’’ جیسے ان کے باپ کو مسح کر ے.ویسے ہی ان کو بھی مسح کر نا.تا کہ وہ میرے لئے کاہن کی خدمت کوانجام دیں.اور ان کا مسح ہو نا ان کے لئے نسل در نسل ابد ی کہا نت کا نشان ہو گا.‘‘ پس بے شک ہر اہل میں خو بیوں کا مو جود ہونا ضروری نہیں مگر مو سٰی اور ہارونؑ کے متعلقین اور ان کے خا ص متبعین میں اللہ تعا لیٰ نے اعلیٰ درجہ کے اخلا ق یقینی طور پر ودیعت کر دئیے تھے.اور طا لو ت کے خدائی انتخاب کا یہ ثبوت بتا یا گیا تھا کہ اللہ تعا لیٰ نے جوروحا نیت آل مو سٰی اور آل ہارونؑ میں رکھی تھی اور جن بلند اخلا ق اور کر دار کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا وہی تقویٰ اور وہی روحا نیت اور وہی بلند اخلا قی طا لوت کے ساتھیوں میںبھی پیدا کر دی جائےگی اور یہ اس بات کا ثبوت ہو گا کہ جس شخص کی انہوں نے متا بعت اختیار کی ہے وہ خدا تعالیٰ کا فر ستادہ ہے.فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ١ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر نکلا تو اس نے کہا کہ اللہ (تعالیٰ )ایک ندی کے ذریعہ سے یقیناً تمہارا امتحان بِنَهَرٍ١ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ١ۚ وَ مَنْ لَّمْ لینے والا ہے.پس جس نے اس( نہر) میں سے (پیٹ بھر کر پانی) پی لیا وہ مجھ سے (وابستہ) نہیں (رہے گا ) يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْۤ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ١ۚ اور جس نے اس سے نہ چکھا وہ یقیناً مجھ سے (وابستہ )ہو گا.سوائے اس کے جس نے اس میں سے (فقط )اپنے فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ١ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَ الَّذِيْنَ ہاتھوں سے ایک چلّو لے (کر پی) لیا( کہ اس پر کوئی الزام نہ ہو گا) پھر ( ہوایہ کہ )ان میں سے چند ایک کے سوا (باقی اٰمَنُوْا مَعَهٗ١ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَ سب نے )اس میں سے (پانی) پی لیا.پھر جب وہ خود اور (نیز )وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس ندی
Page 419
جُنُوْدِهٖ١ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ١ۙ سے پار اتر گئے( تو) انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کی بالکل طاقت نہیں (مگر) كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ١ؕ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ (ایک دن )اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ کے وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۰۰۲۵۰ حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آچکی ہیں.اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ (ہوتا) ہے (پس ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں).حلّ لُغات.اِغْتَرَفَ اِغْتَرَفَ غُرْفَۃً بِیَدِہٖ غر فہ کا لفظ چو نکہ کئی معنوں میں استعمال ہو تا ہے اس لئے اس کے ساتھ یَدٌ بمعنی ہاتھ رکھ دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے معنے محدود ہو گئے ہیں.پس اِغْتَرَفَ غُرْ فَۃً کے معنے اس جگہ صرف چلو بھر لینے کے ہی ہیں.(اقرب) کَمْ یہ لفظ اس جگہ کثرت کے اظہار کےلئے استعمال ہوا ہے.یعنی کتنے ہی ایسے گروہ ہیں جو قلیل ہو نے کے باوجود دوسروں پر غالب آئےلیکن بعض لو گو ں نے کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس سے کثرت مراد ہو بلکہ کسی قدر تعداد کا پایا جا نا بھی کا فی ہے خواہ ایسے گر وہوں کی تعداد تھوڑی ہی ہو.(رازی زیر آیت ھٰذا) فِئَۃٌ جما عت کو کہتے ہیں.یہ لفظ فَاءَ سے نکلا ہے جس کے معنے جھکنے کے ہیں.چو نکہ جما عت بھی ایک دوسرے کی مدد پر بھروسہ کر تی ہے.اور اس کے افراد بھی ایک دوسرے کی طرف جھکتے ہیں.اگر ایک کو دکھ ہو تو وہ دوسرے پر اعتماد کر تا ہے اس لئے اسے فِئَۃٌ کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.جب طا لوت اپنے لشکر کو لے کر جا لوت کے مقا بلہ میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کاایک نہر کے ذریعے پھر امتحان لیا.تا کہ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ الگ ہو جائیں اور صرف وہی لوگ دشمن کے مقا بلہ میں صف آ راء ہوں جو کامل الا یمان ہوں اور جن کی تا ئید میں ملا ئکہ کام کر رہے ہوں.نہر کا تر جمہ ندی کیا گیا ہے.لیکن ھاء کی زبر سے جب یہ لفظ ہو تو اس کے دو معنے ہو تے ہیں.ندی بھی اور فر اخی اور وسعت بھی (مفردات) اس آ یت میں
Page 420
یہ دونوں معنے لگ سکتے ہیں.اگر فر اخی اور وسعت کے معنے لئے جا ئیں تو آ یت کا یہ مطلب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے ذریعہ سے فو جیوں کو اس امر کی اطلا ع دی کہ تمہارا امتحان مال و دولت کی فرا خی سے لیا جائےگا.اگر تم مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے تو خدا تعالیٰ کا کام نہ ہو سکے گا.اور اگر تم مال و دولت سے متا ثر نہ ہوئے تو تم کو کا میا بی ہو گی.اس صورت میں فَمَنْ شَرِبَ مِنْہُ وغیرہ الفا ظ مجا زی معنو ں میں سمجھے جائیںگے لیکن چو نکہ ظاہری رنگ میں بھی طالوت کے سا تھیوں کا ایک نہر کے ذریعہ سے امتحان لیا گیا تھا.ا س لئے ظاہری معنے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں.چو نکہ جنگ میں جلدی اور تیز حرکت کی ضرورت ہو تی ہے.اور پیٹ کا پا نی سے بھر لینا تیز حرکت سے انسان کو محروم کر دیتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیاکہ ہلکے پیٹ رہو.اور پانی کم پیئو.تا کہ جنگ میں عمدگی سے کام کر سکو مگر اکثر لو گو ں نے اس حکمت کو نہ سمجھا اور خوب پیٹ بھر کر پا نی پیا.اور بہت تھوڑی سی تعداد نے جو با ئیبل کے بیا ن کے مطا بق صرف تین سو تھی(قاضیوں باب ۷ آیت ۶) جنگی ضرورتوں کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے یو نہی چند گھونٹ پانی پیا تا کہ لڑائی کے وقت وہ اچھی طرح کام کر سکیں.اللہ تعالیٰ نے ان کی قر بانیوں کا بدلہ دینے کے لئے اور ان کے اخلا ص کی قدر کرنے کے لئے فیصلہ کیا کہ صرف انہیں کے ہاتھ پر فتح ہو اور حکم دیاکہ انہی تین سو کو جنگ میں شامل کیا جائے باقی کو نہیں.چنا نچہ انہی تین سو کو طا لوت نے جنگ میں شا مل کیا اوراللہ تعالیٰ نے انہی کے ہا تھ پر فتح عطا فرمائی.كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ میں بتا یا گیا ہے کہ کتنی ہی چھو ٹی چھو ٹی جماعتیں ہو تی ہیں جواللہ تعالیٰ کےفضل کے ما تحت بڑی بڑی جما عتوں پر غالب آ جا یا کر تی ہیں.اس غلبہ کی وجہ یہی ہو تی ہے کہ ان میں قر بانی اورایثار کا ما دہ ہوتا ہے وہ اپنا وقت ضا ئع کر نے کی بجا ئے اُسے مفید کاموں میں صرف کرنے کے عادی ہوتے ہیں.اُن میں دیا نت بھی ہو تی ہے.صداقت بھی ہو تی ہے.محنت کی عادت بھی ہو تی ہے پھر ان کے حو صلے بلند ہوتے ہیں.ان کے ارادے پختہ ہو تے ہیں اور ان کے مقا بل میں جو لوگ کھڑے ہو تے ہیں وہ ان اوصاف سے خا لی ہو تے ہیں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلیل غالب آ جاتے ہیں اور کثیر مغلوب ہو جا تے ہیں.حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک آ دمی جس میں ایثار کا مادہ ہو تا ہے.درجنوں پر بھاری ہوتا ہے.پا گل کوہی دیکھ لو.لوگ اس کا مقا بلہ کر نے سے گھبراتے ہیں.حالانکہ وہ اکیلا ہوتا ہے.اس کی وجہ یہی ہے کہ لو گ ڈرتے ہیں کہ انہیں چوٹ نہ آ جا ئے.ان کو زخم نہ لگ جا ئے.اور وہ اپنی طا قت کو صرف ایک حد تک استعمال کرتے ہیں.لیکن پاگل کے لئے چوٹ اور زخم بلکہ موت کا بھی کو ئی سوال نہیں ہوتا.اس لئے وہ اپنی طاقت اس حد تک استعمال کر تا ہے
Page 421
جس حد تک ایک سمجھ دار انسان استعمال کر نے کےلئے تیار نہیں ہوتا.اور وہ اکیلا ہو نے کے باوجود دوسروں پر غالب آجاتا ہے.اسی طرح اگر کسی جماعت کے افراد میں قر بانی اور ایثار کا مادہ ہو اور وہ دین کے لئے اپنے اندر مجنو نا نہ رنگ رکھتے ہوں اور وہ اپنی محنت اور قر بانی کو اس حد تک پہنچا دیں کہ جس حد تک پہنچا نے سے دوسرے لوگ گھبرا تے ہوں تو پھر ان کے ایک ایک آ دمی کے مقا بلہ میں دس دس پندرہ پندرہ بلکہ بیس بیس آ دمی بھی ہیچ ہو جا تے ہیں.جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا غزوہ خندق میں بھی ایسا ہی ہوااور مسلما نوں کی ایک چھوٹی سی جماعت اپنے سے کئی گنا بڑی جماعت پر غالب آ گئی.وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں (کے مقابلہ )کے لئے نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے ربّ ! ہم پر قوت ِ برداشت عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ نازل کر اور (میدان جنگ میں) ہمارے قدم جمائے رکھ.اور( ان) کافروں کے خلاف ہماری مدد کر.الْكٰفِرِيْنَ ۰۰۲۵۱فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ١ۙ۫ وَ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ پھر (وہ جنگ میں کود پڑے اور) انہوں نے اللہ کے ارادہ کے مطابق انہیں شکست (دے )دی.اور داؤد نے وَ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ١ؕ وَ لَوْ جالوت کو قتل کیا.اور اللہ نے اسے حکومت اور حکمت بخشی.اور جو کچھ اسے( یعنی اللہ کو) منظور تھا اس کا علم اسے لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ١ۙ لَّفَسَدَتِ (یعنی داؤد کو)عطا کیا.اور اگر اللہ انسانوں کو (شرارت سے) نہ ہٹائے رکھتا.یعنی بعض( انسانوں) کو بعض کے ذریعہ سے الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۰۰۲۵۲ (نہ روکتا)تو زمین تہ و بالا ہو جاتی.لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے (اس لئے اس فساد کو روک دیتا ہے).حلّ لُغات.بَرَزَ کے معنے ہیں خَرَجَ.با ہر نکلا.(اقرب)
Page 422
اَفْر غْ عَلَیْنَا صَبْرًا فَرَ غَ کے معنے ہیں.بہا دیا.انڈیل دیا.پس اَفْرِ غْ عَلَیْنَا صَبْرًا کے معنے یہ ہوںگے کہ ہمیں صبر میں سے وافر حصہ دے یعنی ایسا ہو کہ ہم کا مل طور پر صبر کرنے والے ہوں.اور ہماری کسی حرکت سے جزع فزع ظاہر نہ ہو.اُنْصُرْ نَا:نَصَرَ الْمَظْلُوْ مَ کے معنے ہو تے ہیں اَعَا نَہٗ اُ س نے مظلوم کی مدد کی.اور نَصَرَ فُلَانٌ عَلٰی عَدُوِّہٖ کے معنےہیں نَجَّا ہُ مِنْہُ وَخَلَّصَہٗ وَ اَعَا نَہٗ وَ قَوَّ اہُ عَلَیْہِ.اسے دشمن سے نجات دی.اُس کے پنجے سے چھڑایا اُس کی مدد کی اور اس پر غلبہ بخشا.(اقرب) تفسیر.فر ما تاہے جب مقا بلہ ہوا تو طا لوت اور اس کے سا تھیوں نے جا لوت اور اس کے لشکر کواللہ تعالیٰ کے اذن کے ما تحت شکست دےدی.مفردات میں لکھا ہے کہ اذن کے معنے اجازت اور علم کے ہو تے ہیں.نیز لکھا ہے کہ وَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِیُطَاعَ بِاِ ذْنِ اللّٰہِ میں اِذن سے مراد اس کی مشیت اور حکم ہے.اسی طرح لکھا ہے کہ اذن میں مشیت کا پا یا جا نا ضروری ہو تا ہے جو علم کے لئے ضروری نہیں.ہاں اِذن میں رضا کا ہو نا ضروری نہیں صرف مشیت کا ہوناضروری ہے.اس جگہ اِذن سے مراد مشیت ہی ہے.یعنی اللہ تعالیٰ کے منشاء اور اس کے ارادہ کے مطابق طالوت نے جا لوت کو شکست دے دی.یہ کیا وا قعہ ہے جس کا گزشتہ رکوع سے ذکر چلا آ رہا ہے؟ اس بارہ میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا ہے یہاں تک کہ عیسا ئیوں نے بھی اعتراض کیا ہے کہ قرآن نے دو مختلف زما نوں کے وا قعات کو اکٹھا بیان کر دیا ہے.پرانے مفسّرین کا خیال تھا کہ اس کا مصداق ساؤل ہے جو ایک با دشاہ تھا(جامع البیان زیر آیت ھٰذا) جسے سموایل نبی کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا.اور جا لوت اس کے دشمنوں میں سے تھا.اس میں کو ئی شبہ نہیں کہ با ئیبل میں سا ؤل کے قدوقا مت کا خاص طور پر ذکرکیا گیا ہے.اور لکھا ہے کہ.’’ بنی اسرا ئیل کے درمیان اُس سے خوبصورت کو ئی شخص نہ تھا.وہ ایسا قدآ ور تھا کہ لو گ اس کے کندھے تک آ تے تھے.‘‘(۱.سموائیل باب۹ آیت۲) اور یہ بھی ذکر آ تا ہے کہ وہ ایک ادنیٰ قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا.(۱.سموایل باب ۹ آیت ۲۱).مگر با ئیبل سے ہی ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ سا ؤل سے نا راض ہوا اور اس نے بنی اسرا ئیل کی بادشاہت اس سے چھین لی.(۱.سموائیل باب ۱۵.آیت۲۶) اسی طرح با ئیبل سے یہ بھی ثابت ہے کہ ساؤل نے فلستیوں کے مقا بلہ میں شکست فا ش کھا ئی اور انہوں نے
Page 423
اس کے تین بیٹوں کو مار ڈالا.اور وہ خود بھی خود کشی کر کے مر گیا.(۱.سمو ائیل باب ۳۱ آ یت ۱تا ۵) حا لا نکہ قر آ ن کریم یہ کہتا ہے کہ فر شتے اس کی مدد کر تے تھے.گو یا اسے فتح پر فتح حا صل ہو تی تھی.پس اگر ساؤل کو ہی اس کا مصداق قرار دیا جا ئے تو قر آ نی علا مات اس پر چسپاں نہیں ہو تیں.میں نے جب اس واقعہ پر غور کیا تو مجھے وہ معنے پسند آ ئے جس پر دشمنوں نے اپنی نا دانی سے اعتراض کیا ہے.ان کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم نے دو علیٰحدہ علیٰحدہ زما نوں کے وا قعات کو ملا کر بیا ن کر دیاہے.اور مفسرین نے یہ کو شش کی ہے کہ وہ داؤد اور جالوت اور طالوت کا ایک ہی زما نہ ثابت کریں.سا ؤل پر وہ اس وا قعہ کو اس لئے بھی چسپاں کر تے ہیں کہ وہ لمبے قد کا تھا اور دشمن کے ایک بڑے پہلوان کا نا م جا تی جو لیت( یعنی جا لوت) تھا.(۱.سموایل باب ۱۷ آیت ۴) مگر میرے نزدیک کسی شخص کی تعیین کر نے سے پہلے ضروری ہے کہ قر آ ن کریم کے بیان کر دہ وا قعات پر یکجائی نظر ڈالی جائے.قرآن کر یم میں اس واقعہ کے متعلق پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَ اَ بْنَآ ئِ نَا ہم اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے علیٰحدہ کئے گئے ہیں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم جس کا یہا ں ذکر ہے اپنے گھروں سے نکا لی گئی تھی.دوم.ان پر ایک ایسا شخص بادشاہ بنا یا گیا تھا جو کسی اعلیٰ خا ندان یا شا ہی نسل میں سے نہیں تھا.سوم.وہ ایسا شخص تھا جس کی اللہ تعالیٰ مدد کر تا تھا اور جس کے سا تھی بھی منصور من اللہ تھے اور ان کے پاس ایک تا بوت تھا.چہا رم.ایک نہر کے ذریعہ ان کی آ زمائش ہو ئی تھی.پنجم.ان کی اور ان کے دشمنوں کی تعداد میں بڑا بھا ری فرق تھا.ان کی تعداد دشمن کے مقا بلہ میں بہت ہی تھوڑی تھی اور پھر اس آ زمائش کی وجہ سے اس کی جماعت اور بھی کم ہو گئی.ششم.با وجود اس کے کہ اس کی فوج دشمن کی فو ج سے کم تھی وہ دشمن پر غالب آیا.ان میں سے بعض با تیں بیشک سا ؤل پر بھی چسپاں ہوتی ہیں.مثلاً سا ؤل کے مقرر کر نے میں ایک نبی کا دخل تھا.ساؤل کو اپنے دشمنوں پر فتوحات بھی حاصل ہوئیں.ساؤل کے ایک دشمن کا نام جا لوت بھی تھا.مگر میرے نزدیک اس میں جو با تیں وزنی ہیں اور جن کی وجہ سے ساؤل کی بجا ئے کسی اور شخص کی تلا ش ہما رے لئے ضروری ہے وہ یہ ہیں.اوّل.اس میں مِنْ بَعْدِ مُوْسٰی کے الفا ظ آتے ہیں.میرا ذہن ان الفا ظ سے اس طرف منتقل ہو تا ہے کہ اس میں کسی ایسے زما نہ کا ذکر ہے.جہاں سے بنی اسرائیل کی تا ریخ شروع ہو تی ہے.ورنہ داؤد کے ذکر سے بنی اسرائیل تو وہ آ پ ہی ثا بت ہو جاتے ہیں.پھر مِنْ بَعْدِ مُوْ سٰی کہنے کی کیا ضرورت تھی.پس درحقیقت یہ الفا ظ ان کی قومی تاریخ کی طرف اشارہ کر نے کے لئے لا ئے گئے ہیں.
Page 424
دوم.تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ کے الفا ظ سے ظاہر ہے کہ اسے ہمیشہ فتح ہی حاصل ہو تی تھی.مگر ساؤل کو تو شکستیں بھی ہو ئیں اور پھر اس کا انجا م نہا یت حسر ت ناک ہوا(۱.سموئیل باب ۳۱ آیت ۱ تا ۱۳).حالا نکہ قر آ ن کر یم کے بیان کے مطا بق ضروری ہے کہ اس کا مصداق ہمیشہ فتح پا تا رہا ہو.سوم.اس جگہ مُبْتَلِیْکُمْ بِنَھَرٍ آ یا ہے اور بتا یا گیا ہے کہ ان لو گوں کی ایک نہر کے ذریعہ آ زما ئش کی گئی تھی مگر سا ؤل کے زما نہ میں کسی نہر کے ذریعہ لو گوں کا امتحان لئے جا نے کا بائیبل میں کوئی ذکر نہیں آ تا.پس ہمیں اس شخص کی تلا ش کے ساتھ نہر کے واقعہ کو بھی نظر انداز نہیں کر نا چا ہیے.یہ عجیب بات ہے کہ با ئیبل ایک نہر کا ذکر ضرور کر تی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے ذریعہ ایک قوم کی آزمائش کی گئی.ان کو صاف طور پر کہا گیا تھا کہ تم اس سے پا نی نہ پیئو.مگر اکثر لو گوں نے پا نی پی لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پا نی پینے وا لے پیچھے رہ گئے اور نہ پینے والے حملہ کر کے دشمن پر غالب آ گئے(قاضیوں باب ۷ آیت ۴ تا ۵).گو یا قر آ نی بیان کی تصدیق ہو جاتی ہے مگر ساؤل کے زما نہ میں با ئیبل ایسا کوئی واقعہ بیان نہیں کرتی.عیسا ئیوں نے اس وا قعہ پر اعتراض کر تے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جد عون کا وا قعہ ہے اور جد عون اور دا ؤد میں دو سو سال کا فا صلہ ہے.مگر قر آن نے ان دونوں وا قعات کو ملا کر بیان کر دیا ہے.گو یا ان کے نزدیک قر آن کریم کا یہ کہنا کہ قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ داؤد نے جا لوت کو قتل کیا غلط ہے.کیو نکہ داؤد اور جا لوت میں دو سو سال کا فر ق تھا اور اس لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ داؤد جا لوت کو قتل کر سکتے.میرے نزدیک جد عون کا وا قعہ جو با ئیبل نے بیان کیا ہے اور قرآ ن کریم کے بیان کر دہ وا قعہ میں صرف اس قدر فر ق ہے کہ بائیبل نے یہ نہیں بتا یا کہ اسے کسی نبی نے مقرر کیا تھا.بلکہ اس میں صرف اتنا لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پاس ایک نبی بھیجا جس نے انہیں کہا کہ خدا تعالیٰ فر ماتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ.’’ تم ان امور یوں کے دیوتاؤں سے جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرنا پر تم نے میری بات نہ مانی.‘‘ (قضاۃ باب ۶ آیت ۱۰) اورپھر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جدعون کو خدا تعالیٰ کا فر شتہ دکھا ئی دیا اور اس نے کہا کہ اُٹھ اور مدیانیوں کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کو چھڑا.(قضا ۃ باب۶ آ یت ۱۴) با قی تمام واقعات جو قر آن کریم نے بیان کئے ہیں وہ با ئیبل میں مو جو د ہیں.یہ امر یا د رکھنا چا ہیے کہ حضرت مو سیٰ علیہ السلام کی وفات کا زمانہ ۱۴۵۱ قبل مسیح ہے.اور جدعون کا وا قعہ
Page 425
مو سیٰ علیہ السلام کی و فات کے بعد ۱۲۶۶ قبل مسیح میں ہوا.گو یا ان دونوں میں دو سو سال کا فا صلہ ہے.اور انسائیکلوپیڈیا ببلیکا میں لکھا ہے کہ اس وقت جب بنی اسرائیل مصر سے آئے کنعان میں وہ ایک قوم نہیں بنے بلکہ الگ الگ قبیلوں نے جُداجُدا زمینوں میں اپنی ریا ستیں قائم کر لی تھیں.اس وقت ان میں کوئی با دشاہت نہیں تھی بلکہ دو سو سال تک ان میں کوئی بادشاہت قا ئم نہیں ہوئی.نہ ان میں فو جیںتھیں اور نہ ان کا کوئی با دشاہ تھا.پھر بائیبل میں ۱۲۵۶ قبل مسیح کے متعلق لکھا ہے.’’ بنی اسرائیل نے خدا وند کے آ گے بدی کی تب خدا وند نے انہیں سات برس تک مد یا نیوں کے قبضہ میں کر دیا.اور مد یا نیوں کا ہاتھ بنی اسرائیل پر قوی ہوا اور مد یا نیوں کے سبب بنی اسرائیل نے اپنے لئے پہاڑوں میں کھوہ اور غار میں مضبوط مکا ن بنا ئے.‘‘( قاضیوں باب ۶ آیت ۱،۲) یہ وا قعہ بعینہٖ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ اَبْنَآىِٕنَا سے ملتا جلتا ہے.آگے لکھا ہے.’’ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مد یا نی اور عما لیقی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آ تے تھے اور ان کے مقا بل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیدا وار کو بر باد کر ڈالتے.اور بنی اسرائیل کے لئے نہ تو کچھ معاش نہ بھیڑ بکری نہ گا ئے بیل نہ گدھا چھوڑتے.‘‘ (قا ضیوں باب ۶ آیت ۴) اس کے بعد لکھا ہے.’’ بنو اسرائیل مدیانیوں کے سبب نہایت مسکین ہوئے.اور بنی اسرائیل خدا وند کے آ گے چلا ئے.‘‘ (قاضیوں باب ۶ آیت ۶) ’’ اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے خدا وند سے فر یاد کر نے لگے تو خداوند نے بنی اسرائیل پاس ایک نبی بھیجا جس نے انہیں کہا کہ خدا وند اسرائیل کا خدا یوں فر ماتا ہے کہ میں تم کو مصر سے چھڑا لایا.اور میں تمہیں غلاموں کے گھر سے نکال لایا اورمیں نے مصریوں کے ہاتھ سے اور ان سب کے ہاتھ سے جو تمہیں ستاتے تھے.چھڑایا اور تمہارے سا منے سے انہیں دفع کیا اور ان کا ملک تم کو دیا اور میں نے تم کو کہا کہ خدا وند تمہارا خدا میں ہوں سو تم ان اموریوں کے معبودوں سے کہ جن کے ملک میں بستے ہو مت ڈرو.پر تم میری آ واز کے شنوا نہ ہوئے.‘‘( قا ضیوں باب۶ آیت ۷ تا ۱۰) اس حوالہ میں ایک نبی کا ذکر تو ہوا ہے مگر یہ ذکر نہیں کہ اس نبی نے کوئی بادشاہ مقرر کیا ہو.صرف اتنا ذکر ہے کہ ’’پھر خدا وند کا فرشتہ آیا.....اور اس وقت جدعون مےکے کو لھو کےپاس گہوں جھا ڑ رہا تھا.
Page 426
کہ مدیا نیوں کے ہاتھ سےا نہیں بچاوے.سو خدا وند کا فرشتہ اسے دکھائی دیا اور اس سے کہا کہ خدا وند تیرے ساتھ ہے.اے بہا در پہلوان! جدعون نے اسے کہا.اے ما لک میرے! اگر خدا وند ہمارے ساتھ ہے تو ہم پریہ سب حا دثےکیوں پڑے اور کہاں ہیں اس کی وے سب قدرتیں جو ہمارے باپ دادوں نے ہم سے بیان کیں.اورکہا کیا خدا وند ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا.لیکن اب خداوند نے ہم کو چھوڑدیا.تب خدا وند نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ اپنی اس قوت کے ساتھ جاکہ تو بنی اسرا ئیل کو مدیا نیوں کے ہاتھ سے رہا ئی دےگا.کیا میں تجھے نہیں بھیجتا اور اس نے اسے کہا.اے میرے مالک! میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچا ؤں.دیکھ کہ میرا گھرانا منسّی میں حقیر ہے اور میں اپنے باپ دادوں کے گھرانے میں سب سے چھوٹا ہوں تب خدا وند نے اسے فر مایا کہ میں تیرے ساتھ ہوںگا.اور تو مدیانیوں کو ایک ہی آ دمی کی طرح مارلےگا.‘‘ (قضاۃباب۶آیت۱۱تا ۱۶) قر آن کر یم میں بھی جُنُوْد کا لفظ آ تا ہے اور با ئیبل بھی بتا تی ہے کہ وہاں مدیا نی.عمالیقی اور مشرقی تین قو میں موجود تھیں.پھرلکھا ہے.’’ تب خدا وند نے جد عون کو فر ما یا کہ لوگ ہنوز زیادہ ہیں.سو تو انہیں پا نی پاس نیچے لا کہ وہاں میں تیری خا طر انہیں آ زماؤںگا.‘‘ (قضا ۃ باب ۷ آیت ۴) ’’ سو وہ ان لو گوں کو پا نی پاس نیچے لایا.اور خداوند نے جدعون کو فر مایا کہ جو شخص پا نی چپڑ چپڑکر کے کتّے کی ما نند پیوے تو ہر ایک ایسے کو علیحدہ رکھ.اورویسے ہر ایک کو بھی جو اپنے گھٹنوں پر جھک کے پیوے.سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ کے پاس لا کے چپڑ چپڑ کر کے پیا.وہ گنتی میں تین سو مرد تھے....تب خداوند نے جدعون کو کہا کہ میں ان تین سو آ دمیوں سے جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا تجھے رہائی بخشوںگا.اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کردوںگا.اور باقی سب لو گوں میں ہر ایک کو اس کے مکان پرپھر جانے دو.تب ان لو گوں نے اپنا تو شہ اور اپنے نر سنگے ہاتھوں میں اٹھا ئے اور با قی سب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک کو اس کے خیمے میں بھیجا اور ان تین سو کو اپنے پاس رکھا.اور مدیانیوں کا لشکر اس کے نیچے وادی میں تھا.‘‘ (قضا ۃ باب ۷آیت ۵تا ۸) آ خر میں مد یا نیوں سے نجات پا نے کا ذکر ہے.اور وہ اس طرح کہ جدعون کے ساتھ تین سو آدمی رہ گئے جن کو ساتھ لے کر وہ لڑا اور فتح حاصل کی.یہ سارا واقعہ قرآن کریم سے حرف بحرف ملتا ہے.اور اس کی بخاری کی ایک
Page 427
روایت سے بھی تائید ہو تی ہے.براء بن عازبؓ بیا ن کر تے ہیں کہ کُنَّا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلّمَ نَتَحَدَّثُ اَنَّ عِدَّۃَ اَصْحَابِ بَدْرٍعَلٰی عِدَّۃِ اَصْحَا بِ طَا لُوْتَ الَّذِیْنَ جَا وَزُوْامَعَہُ النَّھْرَوَلَمْ یُجَا وِزْ مَعَہٗ اِلَّا مُؤْمِنٌ بِضْعَۃُعَشَرَوَثَلاَثُ مِا ئَۃٍ.یعنی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے.کہ بدر والوں کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کی تعداد کے مطا بق تھی جو اس کے ساتھ نہر سے گزرے تھے اور ان کے ساتھ تین سو دس سے کچھ اوپر مو من تھے.(بخاری کتاب المغازی باب عدۃ اصحاب بدر) اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو اس کا نام طالوت آ یا ہے اور بائیبل کے حوالہ میں جد عون نام آ یا ہے.ان میں مطا بقت کس طرح ہے؟ سو پہلے میں جدعون کو لیتا ہوں.یہ عجیب بات ہے کہ جدعون کے لفظ کے بھی وہی معنے ہیں جو عربی زبان میں طالوت کے ہیں.جدعون کے معنے عبرانی زبان میں کاٹ کر نیچے گرا دینے کے ہیں یا تراشنے یا کلہاڑے سے کاٹ دینے کے ہیں.پس جد عون ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مخالف کو کاٹ ڈالتا اور زمین پر گرا دیتا ہے.بائیبل میں جدعون کو زبر دست سورما اور بہادر پہلوان کے نام سے پکارا گیا ہے.(دیکھو قضاۃ باب ۶ آ یت۱۱) اور طا لوت جو جدعون کا صفاتی نام ہے اس کے بھی یہی معنے ہیں کیو نکہ طَالَ کے معنے دوسروں سے بلند اور بڑائی والا ہو جا نے کے ہیں.پس طا لوت کے معنے ہیں جو دوسرے سے درجہ اوربڑائی میں اونچا ہو گیا تھا اور دوسروں کو اس نے نیچا کر دیاتھا.گو یا اس نام میں بتا یا گیا ہے کہ پہلے تو وہ ادنیٰ اور معمولی درجہ کا آ دمی تھا مگر پھر بڑا ہوگیا اور خدا تعالیٰ نے اس کو اونچا کر دیا.اور اس قسم کے صفا تی نام قرآن کریم میں بعض اور جگہ بھی استعمال ہوئےہیں.مثلاًاللہ تعالیٰ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فر ما تاے.وَ اَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا(الجن : ۲۰) یعنی جب اللہ تعالیٰ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بلا نے کے لئے کھڑا ہو تا ہے تو مکہ کے لوگ اس پر جھپٹ کر آ گر تے ہیں.اس جگہ عبد اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بیان کیا گیا ہےحالانکہ آپ ؐ کا نام محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) تھاپس جس طرح عبداللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے.اسی طرح طالوت بھی جد عون کا صفا تی نام ہے اور دونوں ہم معنی الفا ظ ہیں.اب صرف جا لوت کالفظ تحقیق طلب رہ گیا.سو یاد رکھنا چا ہیے کہ جالوت بھی ایک صفا تی نام ہے جو کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ ایک گر وہ کا نام ہے جس کا کام ملک میں فساد کر نا اور ڈاکے ڈالنا تھا.جا لوت کوانگریزی زبان میں گو لیتھ کہتے ہیں.اور گو لیتھ کے معنے انگر یزی میں.Destroyers Spirits Sunning Ravaging
Page 428
کے ہیں.یعنی تباہی اور بر بادی ڈھا نے اور لوٹ مار مچانےوالی روحیں.جو اِدھر اُ دھر دوڑتی پھر تی ہوں.اور جا ئل جو اصل میں جا لوت ہے اس قوم کو کہتے ہیں جو ہر طرف قتل وغارت اور تبا ہی و بر بادی کا بازار گر م کر نے والی ہو.بائیبل سے بھی ثابت ہے کہ جدعون کا دشمن ایک آ وارہ گرد گروہ تھا جو ملک میں فساد پھیلاتا پھر تا تھا.چنا نچہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جب حملہ کر تے تھے تو سب کچھ بر باد کر دیتے تھے.پس یہاں جالوت سے کو ئی ایک شخص مرادنہیں بلکہ ایک گروہ مراد ہے.جس نے بنی اسرائیل پر عرصہء حیات تنگ کر رکھا تھا.بائیبل بتا تی ہے کہ جد عون نے ان کو شکست دی اور اس کے بعد ستر سال تک اس کی حکومت رہی.یعنی چا لیس سال تک وہ خود حکومت کر رہا اور تیس سال تک اس کا بیٹا.اور اس کے نتیجہ میں متحدہ قومیت کی روح یہود میں تر قی کر گئی(قضاۃ باب ۸ آیت ۲۸).اس کے بعد فر ما تا ہے.وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ داؤد نے جا لوت کو قتل کر دیا.یہاں جدعون کے واقعہ کے تسلسل میں ایک نیا واقعہ حضرت داؤدعلیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام کا واقعہ جدعون کے واقعہ سے بہت کچھ ملتا ہے جدعون کے وقت فلسطینیوں نے اسرائیل کو فلسطین سے نکالنے کی بےشک کو شش کی تھی.اور جدعون نے ان کا مقا بلہ کیا اور انہیںشکست دی(قضاة باب ۸ آیت ۱ تا ۱۲).لیکن وہ ابتدائی کو شش تھی جو حضرت داؤدعلیہ السلام کے زما نہ میں آ کر ختم ہوئی.اور انہوں نے دشمن کو کلّی طور پر تباہ وبرباد کر دیا.پس اس واقعہ کو مشابہت مضمون کی وجہ سے اس کے سا تھ بیان کیا گیا ہے.ورنہ پہلا جد عون کا واقعہ ہے.اوریہ داؤد ؑکا واقعہ ہے اور دونوں میں دو سو سال کا فاصلہ ہے.اب صرف ایک سوال حل طلب رہ جاتا ہے.اور وہ یہ کہ بائیبل کی رو سے تو داؤد نے جا لوت کو قتل کیا تھا.(۱.سمو ایل باب ۱۷ آ یت ۵۰،۵۱) لیکن قرآن کریم نے جد عون کے واقعہ میں بھی جا لوت کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَیعنی جب وہ جا لوت اور اس کی فو جوں کے مقابلہ کےلئے نکلے.تو انہوں نے کہا.اے ہمارے ربّ! ہم پر قوتِ برداشت نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش اور کفار کے خلاف ہماری تائید اور نصرت فر ما.اِس کے متعلق یاد رکھنا چا ہیے کہ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے.جا لوت ایک صفاتی نام ہے.اور اس سے مراد ایسا گروہ ہے جو ملک میں فساد کرتاپھرے اور چونکہ جدعون کا دشمن بھی ایک آ وارہ گرد گروہ تھا جو ملک میں فساد پھیلا تا پھر تا تھا اور حضرت داؤدعلیہ السلام نے ملک میںامن قائم کر نے کے لئے جس دشمن کا مقابلہ کیا وہ بھی آ وارہ گرد اور فسادی تھا.اِس لئے دونوں کے دشمنوں کو صفاتی لحاظ سے جا لوت کہا گیا ہے.اور ان دونوں کا اکٹھا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ
Page 429
جد عون کے ہاتھ سے تو دشمن کو صرف شکست ہوئی تھی مگر داؤدعلیہ السلام کے ہاتھوں ان کی کلّی تباہی ہوئی اور آپ نے انہیں نیست و نا بود کر دیا.گو یا دشمن کے مقا بلہ کی ابتدا جد عون سے ہوئی اور اس کا انتہاء داؤد ؑ پر ہوا.اسی لئے قرآن کریم میں قَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ کے الفاظ آئے ہیں.کہ داؤد نے جا لوت کا خا تمہ کر دیا.اور طا لوت اور اس کے ساتھیوں کے متعلق صرف هَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ کے الفاظ آئے ہیں.یعنی انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دی.تا ریخ سے ثا بت ہے کہ جد عون نے ۱۲۵۶ سنہ قبل مسیح میں مخا لفوں کو شکست دی اور ۱۱۶۱ قبل مسیح تک اس کی اور اس کے بیٹے کی حکو مت رہی.اس کے بعد ۱۰۵۰قبل مسیح میں بنی اسرائیل کا کنعان پر داؤد کے ذریعے قبضہ ہوا.غرض جد عون اور داؤد کے اکٹھا ذکر کر نے اور ان دونوں کے واقعات کو ملا کر بیان کر نے کی یہی وجہ ہے کہ جدعون وہ پہلا شخص ہے جس نے بنی اسرائیل کے دشمنوں کا مقا بلہ کیا.اور یہود میں متحدہ قومیت کی روح پھو نکی.اور داؤد علیہ السلام آ خری شخص ہیں جن کے ہاتھوں دشمن کی کلّی تباہی ہوئی غرض جدعون پہلا نقطہ ہے اور داؤد آ خری نقطہ.وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ١ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.میں بتا یا کہ اگر ہم شریروں کابعض دوسرے انسانوں کے ذریعے قلع قمع نہ کر تے تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا.یہ اس لئے فر ما یا کہ جد عون اور داؤد دونوں کی جنگیں مذہبی تھیں.کیونکہ ان کے دشمن ان کی عبادت گاہیں گرا کر ان کی جگہ اپنی عبادتگاہیں بنا دیتے تھے.جیسا کہ جد عون کے متعلق قا ضیوں باب ۶ اور داؤد کی نسبت ۲.سموایل سے ثابت ہے.چو نکہ اسلام کو بھی مذہبی جنگوں کا سا منا کرنا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جدعون اور داؤد کے واقعات پیش کر کے مسلمانوں کو تو جہ دلائی کہ اب تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور شریروں کا مقابلہ کرو اور دنیا میں نیکی اور تقویٰ پھیلاؤ کیو نکہ بحروبّر میں فساد بر پا ہو چکا ہے.اور اس امر کو یادرکھو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جدعون اور داؤد کو مدد دی تھی اسی طرح اب اس کی معجزانہ نصرت تمہارے لئے ظاہر ہو گی.کیو نکہ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے اور امن کبھی قائم نہ ہو.تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ١ؕ وَ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۰۰۲۵۳ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم تجھے پڑھ کر سناتے ہیں اس حالت میں کہ تو حق پر (قائم) ہے اور تو یقیناً رسولوں میں سے ہے.ِ تفسیر.فر ماتا ہے طا لوت اور داؤد کے واقعات ہم نے قصہ کے رنگ میںبیان نہیں کئے بلکہ یہ
Page 430
پیشگوئیاں ہیں جن کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ساتھ بھی یہی واقعات پیش آنے والے ہیں اور ان کو بھی وہی نصرت اور تائید حاصل ہو گی جو پہلے انبیاعلیھم السلام کو حاصل تھی اورا س طرح دنیا پر ظاہر ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے فرستادہ اور اس کے بر گزیدہ رسول ہیں.تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ١ۘ مِنْهُمْ مَّنْ یہ (مذکورہ بالا )رسول وہ ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی تھی.ان میں سے بعض ایسے ہیں كَلَّمَ اللّٰهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ١ؕ وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں بعض کے (فقط) درجات بلندکئے.اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ١ؕ وَ لَوْ شَآءَ کھلے کھلے دلائل دئیے تھے.اور روح القدس کے ذریعہ سے اسے طاقت بخشی تھی.اور اگر اللہ چاہتا تو اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جو لوگ ان کے بعد( آئے) تھے وہ کھلے (کھلے) نشانوں کے آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے (جھگڑتے).جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَ لٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَ لیکن (تعجب ہے کہ )انہوں نے (باوجود اس کے)اختلاف کیا.چنانچہ ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے مِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ١ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا١۫ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اور بعض نے انکار کر دیا.اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے (جھگڑتے) لیکن اللہ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُؒ۰۰۲۵۴ جو چاہتا ہے وہی کرتاہے.تفسیر.فر ما تاہے.یہ رسول جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ایسے ہیںکہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر
Page 431
فضیلت دی تھی.یعنی ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ بلند مقام رکھتے تھے اور بعض نسبتاً کم.یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء کے ذکر پر طبعی طور پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پہلے انبیاء تو ایک ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور ان کا مقابلہ بھی صرف اپنی اپنی قوم کے افراد سے تھا.کو ئی عالمگیر مخالفت ان کی نہیں ہوئی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میں ساری دنیا کے لئے بشیر ونذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں.پھر آ پ ساری دنیا کے مقابلہ میں کس طرح فتح پا سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے کہ پہلے رسولوں میں بھی توآپس میں درجہ اور مقام کے لحاظ سے فرق تھا.یہ تو نہیں کہ سب ایک ہی درجہ رکھتے تھے.آ خر کمال کے بھی ہزاروں درجے ہیں اور خود انبیاء میں بھی مدارج فضیلت میں فرق ہوتا ہے.پس ان میں سے ہو نے کے یہ معنے نہیںکہ ان جیسا ہی درجہ بھی ہو.اور کو ئی فضیلت نہ ہو.مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام جن کا یہاں ذکر کیا گیاہے وہ نبی ہو نے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے.اور اس طرح ان کو بعض انبیاء کے مقابلہ میں ایک ظاہری فضیلت حاصل تھی اسی طرح آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت عطا کی گئی مگر داؤد کی فضیلت تو صرف چند نبیوںپر تھی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب انبیاء پر ہے بلکہ آپ نے تو یہاں تک فر مایا کہ اگر موسیٰ ؑ اور عیسٰیؑ بھی میرے زمانہ میں زندہ ہوتے تو وہ میری اطاعت کرتے(ابن کثیر تفسیر سورۃ ال عمران زیر آیت ۸۲،۸۳).مِنْھُمْ مِنْ کَلَّمَ اللّٰہُ سے بعض لوگوں نے بالمشافہ گفتگو کر نا مراد لیا ہے.یعنی ایسے طریق پر کلام کرتا کہ درمیان میں جبرائیلی واسطہ نہ ہو مگر میرے نزدیکمِنْھُمْ مَنْ کَلَّمَ اللّٰہُ سے تشریعی نبی مراد ہیں اور رَفَعَ بَعْضَھُمْ دَرَجٰتٍ سے غیر تشریعی انبیاء مراد ہیں اس لئے کہ کلام تو ہر ایک رسول سے ہوتا ہے.بغیر کلام کے وہ نبی کیو نکر ہو سکتا ہے اور درجہ بھی ہر ایک کا بلند ہوتا ہے.لیکن جب مقابلہ ہو تو اس کے یہی معنے ہوںگے کہ بعض کو شریعت دی اور بعض کو صرف نبوت کا درجہ دیا گیا.جیسے حضرت عیسٰیعلیہ السلام ہیں ان کو شریعت نہیں دی گئی محض نبوت عطا کی گئی ہے.اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مو سیٰ علیہ السلام کی نسبت فر ما تاہے وَ کَلَّمَ اللّٰہُ مُوْ سٰیتَکْلِیْمًا (النسا ء :۱۶۵) اللہ تعالیٰ نے موسٰی سے خوب اچھی طرح کلام کیا.یہ کہ کَلَّمَ اللّٰہُ کے معنے شریعت کے ہیں اس کا ثبوت ایک حدیث سے بھی ملتا ہے.امام احمدؒ نے ابوذرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.پہلے نبی آدم تھے.وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وَنَبِیٌّ کَانَ.کیا وہ نبی تھے؟ آ پ نے فر ما یا.ہاں! نَبِیٌّ مُکَلَّمٌ ( مسند احمد بن حنبل مسند الانصار حدیث ابی ذر غفاری) وہ مکلَّم نبی تھے.اس سے معلوم ہوا کہ بعض نبی مکلَّم نہیں ہو تے اور چو نکہ اللہ تعا لیٰ نے کلا م تو سب انبیاء سے کیا ہے
Page 432
اس لئے اس جگہ کلام سے مرا د کلام شریعت ہے.اور رَ فَعَ بَعْضَھُمْ دَرَجٰتٍ کے معنے یہ ہیں کہ بعض کو شر یعت نہیں دی.ہاں نبوت کے درجہ رفیع پر ان کو سر فراز فر ما یا.جیسے دوسری جگہ فر ما تاہے وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ.(البقرة: ۸۸) یعنی ہم نے مو سٰیؑکو کتا ب دی اور اس کے بعد ہم نے اس کی تعلیم کی اشاعت کےلئے پے درپے انبیاء بھیجے.یہ تمام انبیاء غیر تشر یعی تھے جو مو سوی شر یعت کے تا بع تھے.پھر فر ماتا ہے وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ہم نے عیسٰی بن مریم کو کھلے کھلے نشانات دئیے اور روح القدس کے ساتھ اس کی تا ئید کی.اس جگہ یہ نکتہ یاد رکھنے والا ہے کہ اس سورۃ میں چو نکہ یہود مخاطب ہیں.اس لئے حضرت مسیح ؑ کے ذکر کے سا تھ ہی ان کی بعض صفات بھی بتا دی جا تی ہیں تا کہ دشمن پر حجت ہو.اس سے ان کی کسی خا ص فضیلت کا اظہار مقصود نہیں ہوتا.جیسا کہ مسیحیوں نے سمجھا ہے.اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ فر ما کر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ئی نئی شریعت نہیں لائے تھے بلکہ انہوں نے تورات کے بعض مضامین کو نمایاں طور پر دنیا کے سا منے پیش کیا تھا اور روح القدس سے اللہ تعا لیٰ نے ان کی تائید فر ما ئی تھی.کیونکہ گو مو سوی دور میں شر لعیت کی تکمیل ہو گئی تھی لیکن آ ہستہ آ ہستہ لو گوں کی نگاہ مغز سے ہٹ کر صرف چھلکے کی طرف آ گئی.پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تا کہ ایک طرف تو تورات کے احکام پر عمل کرا ئیں جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے.’’ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتا بوں کو منسو خ کر نے آ یا ہوں.منسوخ کر نے نہیں بلکہ پورا کر نے آ یا ہوں‘‘.(متی باب ۵ آ یت ۱۷) اور دوسری طر ف وہ لوگ جو با لکل اس کے چھلکے کو پکڑ کر بیٹھ گئے تھے ضروری تھا کہ ان کی اصلاح کی جاتی.اور اس نکتہ کو کھول کر بیان کیا جاتا کہ ظاہری شریعت اس دنیا کی زندگی کو درست کر نے کے لئے اور باطنی شریعت کے قیام میں مدد دینے کے لئےہے.ورنہ اصل چیز صرف با طنی صفائی اورپا کیزگی اور تقدس ہے.سواللہ تعالیٰ نے حضرت عیسٰیعلیہ السلام سے یہ کام لیا.انہوں نے ایک طرف تو مو سوی احکام کو دوبارہ اصل شکل میں قائم کیا اور دوسری طرف جو لوگ قشر کی اتباع کر نے والے تھے انہیں بتا یا کہ اس ظاہر کا ایک با طن ہے.اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو ظاہر لعنت بن جاتا ہے.نما زیں بڑی اچھی چیز ہیں لیکن اگر تم صرف ظاہری نماز ہی پڑھو گے اور با طنی نہیں پڑھو گے تو وہ نماز تمہارے لئے لعنت بن جا ئےگی.(متی باب ۶ آیت ۴ تا ۱۸)روزہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اگر تم ظاہری روزہ کے سا تھ با طنی روزہ نہ رکھو گے تو یہ ظاہری روزہ لعنت بن جائےگا یہ وہی بات ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے
Page 433
ان الفاظ میں بیان فر مائی ہے کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ۠ (الما عون: ۵) یعنی بعض نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز ان کے لئے ویل اور لعنت بن جا تی ہے.مسلمانوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چو نکہ پوری بات کھول کر بتا دی تھی اس وجہ سے انہیں دھوکہ نہ لگا.یہ کھول کر بتا نا بھی حضرت عیسٰی علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطا بق تھا.انہوں نے کہا تھا کہ ’’جب وہ روح حق آ ئے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتا ئے گی اس لئے کہ وہ اپنی نہ کہے گی بلکہ جو کچھ سنے گی سوکہے گی‘‘.(یو حنا باب ۱۶ آیت ۱۳) بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو واضح کر نے کی وجہ سے با وجود اس کے کہ آ پ نے بھی وہی بات کہی تھی جوحضرت مسیح علیہ السلام نے کہی تھی مسلمانوں کو دھو کا نہ لگا.اور انہوں نے شر یعت کو لعنت نہ قرار دیا بلکہ صرف اس عمل پر شر یعت کو لعنت قرار دیا جس کے ساتھ دل کا تقدس اور اخلاص اور تقویٰ شامل نہ ہو.مگر مسیحیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام سے دھوکا کھا یا اور جب ان کی روحانیت کمزور ہوئی تو انہوں نے اپنی کمزوری کے اثر کے ماتحت غلط تاویلوں کا راستہ اختیار کر لیا اور شریعت کو لعنت قراد دینے لگے اور یہ خیال نہ کیا کہ اگر وہ لعنت ہے تو حضرت عیسٰی علیہ السلام اور ان کے حواری روزے کیوں رکھتے تھے عبادتیں کیوں کر تے تھے؟ ان امور سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ ظاہری عبادت کو لعنت نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح نہ کی جا ئے تو وہ ظاہر لعنت بن جاتا ہے.غر ض اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ کے یہ معنے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پا کیزگئ قلب کے خاص راز ظاہر کئے گئے تھے اور قدوسیت اور با طنی تعلیم پر زور دینے کے لئے ان کو خا ص طور پرحکم دیا گیا تھا اور ظاہری احکام کی باطنی حکمتیں انہیں سمجھا ئی گئی تھیں.گویا ان کے دور میں تصوف نے زما نہ بلو غت میں قدم رکھنا شروع کر دیا تھا.وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَ لٰكِنِ اخْتَلَفُوْا میں بتا یا کہ اتنے نبیوں کے واقعات دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ سنبھل جاتے اور آ ئندہ ان کے بارہ میں کو ئی مخالفانہ رویہ اختیار نہ کرتے.لیکن اس رسول کے آ نے پر انہوں نے پھر اختلاف کیا اور بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا.وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا١۫ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ.اور اگر اللہ چا ہتا یعنی لو گوں کو جبراً ہدایت دینا چا ہتا تو کوئی اختلاف نہ ہو تا.مگر چو نکہ انسان کی پیدا ئش کی غرض ہی یہی تھی کہ اسے آ زادا نہ طور پر نیکی اور بدی میں حصہ لینے کا مو قعہ دیاجائے اوراللہ تعا لیٰ یہ فیصلہ فر ما چکا تھا کہ ہم انسان کو خیر کی بھی مقدرت دیںگے اور شرکی بھی اور پھر جو رستہ وہ اختیار کرےگا اس کے مطا بق ہم اسے نیک یا بد جزا دیں گے.اس لئے وہ اس فیصلہ کے مطا بق کام کرتا
Page 434
چلا جاتا ہے اور لو گوں کے اعتراضوں کی پرواہ نہیں کرتا.يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ اے ایمان دارو! جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ کسی قسم کی يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ١ؕ وَ ( خرید و) فروخت نہ دوستی اور نہ شفاعت (کارگر )ہوگی (خدا کی راہ میں جو کچھ ہوسکے)خرچ کر لو.اور الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۰۰۲۵۵ (اس حکم کا )انکار کرنے والے (اپنے آپ پر) ظلم کرنے والے ہیں.حلّ لُغات.خُلَّۃٌ اَلْخُلَّۃُ کے معنے ہیں اَلصَّدَاقَۃُ دوستی اور محبت اور تَخَلَّلَتِ الْقَلْبَ کے معنے ہیں.دَخَلَتْ خِلٰلَہٗ وہ دوستی اور محبت جو دل کے اندر گھس کر اس کے سورا خوں میں داخل ہو جائے.(مجمع البحا ر) اَلْـخَلِیْلُ مَنْ خُلَّتُہٗ مَقْصُوْرَۃٌ عَلٰی حُبِّ اللّٰہِ تَعَا لٰی فَلَیْسَ فِیْھَا لِغَیْرِ ہٖ مُتَّسَعٌ وَلَا شِرْکَۃٌ مِنْ مَحَابِّ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ( مجمع البحار) خلیل اُسے کہتے ہیں جس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سا تھ ہو اور اس کے دل میں اس محبت کے سوا اور کسی کی محبت نہ ہو.حدیث میں آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول درج ہے کہ اِنِّیْ اَبْرَءُ مِنْ کُلِّ ذِیْ خُلَّۃٍ مِنْ خُلَّتِہٖ لَوْ کُنْتُ مُتَّخِذً اخَلِیْلًا لَاتَّخَذْ تُ اَبَا بَکْرٍ.(مسند احمد بن حنبل مسند المکثرین من الصحابۃ مسند عبد اللہ بن مسعودؓ ) یعنی میں ہر شخص کی دوستی سے براء ت کا اظہار کر تا ہوں اور صرف خدا تعالیٰ کی طرف تو جہ کر تا ہوں.اگر دنیا میں مَیں کسی کو خلیل بنا تا تو ابو بکرؓ کو بنا تا.شَفَاعَۃٌ شَفَعَ سے نکلا ہے اور شَفَعَ کے معنے جفت کے ہیں.یُقَالُ شَفَعَ الْعَدَدَ وَشَفَعَ الصَّلٰوۃَ صَیَّرَھَا شَفَعًا.یعنی شَفَعَ الْعَدَدَ کے معنے ہیں عدد کو جفت بنا یا اور شَفَعَ الصَّلٰو ۃَ کے معنے ہیں نماز کو جوڑا بنا دیا.(اقرب) تفسیر.اس آ یت سے ظا ہر ہے کہ اسلام نے صرف زکوٰ ۃ اور مالِ غنیمت کے اموال سے ہی غرباء اور مسا کین کی امداد کے لئے ایک فنڈ مقرر کرنے پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ مسلما نوں کو عام طور پر بھی غر یبوں اور نا داروں کے
Page 435
لئے صدقہ و خیرات کر نے کی بار بار تا کید فرمائی ہے.اور بتا یا ہے کہ تمہارے سا تھ تر قیات کے جو وعدے کئے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں اب مزید قر با نیوں کی ضرورت نہیں قربانیاں تمہیں قدم قدم پر کر نی پڑیں گی اور قدم قدم پر تمہیں اپنے اموال خدا تعالیٰ کی راہ میں خر چ کر نے پڑیں گے.لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَّ لَا شَفَاعَةٌ میں جس بیع کی طرف اشارہ ہے اس کا ذکر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فر مایا ہے اِنَّ اللّٰہَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُئْو مِنِیْنَ اَنْفُسَھُمْ وَ اَمْوَالَھُمْ بِاَنَّ لَھُمُ الْجَنَّۃَ (التو بۃ: ۱۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے مو منوں سے ایک بیع کی ہے اور وہ یہ کہ ان کے مالوں اور جا نوں کو جنت دےکر خرید لیا ہے.پس فر ما یا خدا تعالیٰ تم سے یہ بیع کر تا ہے.مگر یہ بیع اسی دنیا میں ہو گی اس دن نہیں ہو گی.وَ لَا خُلَّةٌ میں بتا یا کہ قیا مت کے دن خدا تعالیٰ کے سوا سب خلیل جا تے رہیں گے.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو دوسری جگہ آ تا ہے اَ لْاَخِلَّاءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ عَدُ وٌّ اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ( الزخرف : ۶۸) یعنی متقیوں کے سوا تمام خلیل ایک دوسرے کے دشمن ہوںگے.پھر جب متقیوں کی دوستی رہے گی تو لَا خُلَّةٌ کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ متقی چو نکہ خدا تعالیٰ کو ہی اپنا خلیل سمجھتے ہیں اس لئے ان کی دوستی خدا تعالیٰ کی دوستی میں شا مل ہو گی اس کا کو ئی علیحدہ وجود نہیں ہو گا جو وَ لَا خُلَّةٌ کے منا فی ہو.اصل مضمو ن جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ آ ج اگر خدا تعالیٰ کو خلیل بنا نا ہے تو بنا لو ورنہ اس دن وہ خلیل نہیں بنے گا.اور آج جن کو تم اپنا خلیل بنا رہے ہو ان کی خلت اور دوستی اس دن تمہارے کسی کام نہیں آ ئےگی بلکہ تم ان کے دشمن بن جاؤ گے.صرف متقی ہی ایسے ہو ںگے جو اپنے خلیل کے دشمن نہیں ہو ںگے کیو نکہ مومن کا خلیل خدا تعالیٰ ہو تا ہے.پس وَ لَا خُلَّةٌ سے مراد وہ خلّت ہے جو خدا تعالیٰ کے مقا بلہ میں کسی دوسرے سے کی جائے.وَ لَا شَفَاعَةٌ میں بتا یا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تم یہیں تعلق پیدا کر لو اور اس کو اپناسا تھی بنا لو.ورنہ وہاں تمہیں کوئی سا تھی نہیں ملے گا.دوسری جگہ فر ما تا ہے وَ اَنْذِرِ بِہِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْۤا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ( الانعام:۵۲) یعنی تو اس کلام کے ذریعہ سے ان لو گوں کو جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے ربّ کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائےگا جب کہ اس کے سوا نہ ان کا کو ئی مدد گار....ہو گا اور نہ کوئی سفا رشی اس لئے ڈرا کہ وہ تقویٰ اختیار کر یں.اسی طرح ایک اور جگہ فر ماتا ہے.وَ ذَكِّرْ بِهٖۤ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ١ۖۗ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ١ۚ وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا (الانعام:۷۱) یعنی تو اس کلام الٰہی کے ذریعہ سے نصیحت کر.تا ایسا نہ ہو
Page 436
کہ کسی جان کو اس کے کمائے ہوئے کے سبب سے اس طرح ہلاکت میں ڈال دیا جائے کہ خدا تعالیٰ کے سوا اس کا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ شفیع.اور اگر وہ ہر ایک قسم کا بدلہ بھی دیں.تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا.ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں خدا تعالیٰ کو ولی اور شفیع بنانےوالوں کو تو اس دن شفاعت کا حق پہنچےگالیکن دوسروں کو نہیں اور نہ ان کے حق میں شفاعت قبول ہو گی.خدا تعالیٰ کو شفیع اس لئے قرار دیا کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی پس اصل شفیع وہی ہے فرما تا ہےيَوْمَىِٕذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهٗ قَوْلًا(طٰہٰ: ۱۱۰) یعنی اس دن شفا عت سوائے اس کے جس کے حق میں شفاعت کر نےکی اجا زت رحمٰن خدا دےگا اور جس کے حق میں بات کہنے کو وہ پسند کرےگا اور کسی کو نفع نہیں دےگی.اس سے ثابت ہو تا ہے کہ وہاں شفاعت بالا ذن ہو گی.خدا تعالیٰ کو شفیع بنانے والوں کو تو شفاعت کا حق پہنچے گا لیکن اور کسی کو خدا تعالیٰ کے اِذن کے بغیر شفاعت کا حق نہیں ہوگا.دوسری جگہ فر ما تا ہے.يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لَا يَشْفَعُوْنَ١ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَ هُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ(الانبیاء: ۲۹) یعنی خدا تعالیٰ اس کو بھی جا نتا ہے جو انہیں آ ئندہ پیش آنےوالا ہے اور جو وہ پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور وہ سوائے اس کے جس کے لئے خدا نے یہ بات پسند کی ہو کسی کےلئے شفاعت نہیں کر تے اور وہ اس کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں.پھر اس آ یت سے اگلی آ یت میں فر ماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ(البقرہ: ۲۵۶) یعنی کون ہے جو اس کی اجا زت کے بغیر اس کے حضور کسی کی سفارش کرے.بیشک حد یثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیا مت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سا بقین کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امتی بھی شفاعت کر یںگے(ابن ماجہ کتاب الزھد باب ذکر الشفاعۃ).لیکن ان حدیثوں کے بارے میں میری تشریح یہ ہے کہ امت محمدیہ میں سے ایسے افراد کی شفاعت صرف ظلّی ہو گی اصل شفیع آ نحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوںگے.وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفا رش کریںگے اور آپ اللہ تعالیٰ سے.با نی سِلسلہ احمد یہ نے بھی اسی عقیدہ کی تو ضیح فر ما ئی ہے آپ اپنی کتاب ’’کشتی توح‘‘ میں فر ما تے ہیں.’’ نوع انسان کےلئے روئے زمین پر اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم.سو تم کو شش کرو کہ سچی محبت اس جا ہ و جلال کے نبی کے ساتھ رکھو اور اس کے غیر کو اس پر کسی نوع کی بڑائی مت دو تا آ سمان پر تم نجا ت یا فتہ لکھے جاؤ.‘‘ (کشتی نوح ،روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۱۵،۱۶) بہر حال جب تک کو ئی انسان اللہ اور اس کے رسول سے و اصل نہ ہو جائے اور ان کو اپنا جوڑا نہ بنا لے اس وقت تک اسے کسی قسم کی شفاعت میسر نہیں آئےگی.
Page 437
وَ الْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَمیںبتا یا کہ یہ ظلم نہیں بلکہ ظلم کفار نے خود اپنی جا نوں پر کیا ہے.اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ١ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ١ۚ۬ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ اللہ وہ (ذات) ہے جس کے سوا پرستش کا( اور) کوئی مستحق نہیں.کامل حیات والا( اپنی ذات میں) قائم (اور سب کو) لَا نَوْمٌ١ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ١ؕ مَنْ قائم رکھنے والا.نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند( کاوہ محتاج ہے).جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ١ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ( سب) اسی کا ہے.کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں سفارش کرے.جو کچھ ان کے سامنے ہے اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ١ۚ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ( سب ہی کچھ )جانتا ہے.اور وہ اس کی مرضی کے سوا اس کے علم کے عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ١ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ١ۚ کسی حصہ کو (بھی)پا نہیں سکتے.اس کا علم آسمانوں پر( بھی) اور زمین پر (بھی )حاوی ہے.وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا١ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ۰۰۲۵۶ اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں.اور وہ بلند شان(رکھنے) والا (اور )عظمت والا ہے.حلّ لُغات.اَلْحَیُّ کامل حیات والا.اللہ تعالیٰ کے لئے جب اَلْحَيُّ آ تا ہے تو الف لام کمال کے معنے دیتا ہے اور اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیاتِ کاملہ رکھتا ہے یعنی ایسی حیات جو اپنے قیام میں کسی اور کی محتاج نہیں.اسے کسی اور نے زندگی نہیں بخشی بلکہ اس کی ذات ازلی اور ابدی طور پر زندہ ہے.اَلْقَیُّوْمُ قَامَ سے نکلا ہے جس کے معنے کھڑے ہو نے کے ہیں.اسی سے قَیِّمٌ نکلا ہے جس کے معنے نگران اور متولّی کے ہیں اور قَیِّمٌ مُسْتَقِیْمٌ کو بھی کہتے ہیں.اَمْرٌ قَیِّمٌ ایسا امر جس میں کوئی کجی نہ ہو بلکہ درست اور ٹھیک ہو.
Page 438
اَلْقَیُّوْمُ اور اَلْقَیَّامُ کے معنے ہیں جو اپنی ذات میں قا ئم ہے اور اس کی کو ئی ابتداء نہیں (اقرب) اَلْقَیُّوْمُ صرف اسی کو نہیں کہتے جو اپنی ذات میں قا ئم ہو بلکہ اس کے معنوں میں دوسرے کو قائم رکھنا اور اس کی حفاظت کر نا بھی شامل ہے.مفردات میں لکھا ہے.اَلْقَائِمُ اَلْحَا فِظُ بِکُلِّ شَیْ ئٍ وَ الْمُعْطِیْ لَہٗ مَا بِہٖ قِوَ امُہٗ یعنی جو اپنی ذات میں قا ئم ہو اور ہر چیز کا نگران ہو اور اسے وہ طاقت عطا کرے جس سے وہ قائم رہ سکے.غر ض اشیاء میں وہ طاقتیں پیدا کر نا جن سے ان کے اجزاء جڑے رہتے ہیں اور اپنے مفوضہ کاموں کو بجا لاتے ہیں قَیُّوْم سے متعلق ہے.اور اللہ تعالیٰ اَلْقَیُّوْمُ ہے.نہ صرف اس لئے کہ وہ خود قا ئم ہے بلکہ اس لئے بھی کہ دوسری سب اشیاء اس کی پیدا کردہ طاقتوں سے قا ئم رہتی ہیں.اَلْقَیُّوْمُ کی صفت اجرام فلکی میں کشش ثقل کے وجود اور خور دبینی ذرات کے ایک دوسرے سے اتّصال اور ایک دوسرے سے ادغام اور ایک دوسرے کے گر د گھو منے وغیرہ افعال پر لطیف رنگ میں اشارہ کر تی ہے.سِنَۃٌ اَلسِّنَۃُ مِنَ الْوَ سْنِ.سِنَۃٌ کا لفظ وَسْنٌ سے نکلا ہے اور وَسَنَ الرَّجُلُ کے معنے ہو تے ہیں اَخَذَہٗ ثِقْلُ النَّوْمِ.اسے گہری نیند نے آ پکڑا جس کی علامت اونگھ ہوتی ہے.پس سِنَۃٌ سے مراد وہ اونگھ ہے جو نیند کے غلبہ کی وجہ سے آنے لگے.(اقرب) اَلنَّوْمُ معمولی نیند جو انسان کو بے اختیار نہ کردے.(مفردات) اَلْکُرْ سِیُّ کِــرْسی سے نکلا ہے جس کے معنے متفر ق اجزاء کے اکٹھا ہو نے کے ہو تے ہیں.کہتے ہیں کَرَسْتُ بِنَاءً.میں نےعمارت بنائی،یعنی اینٹوں پر اینٹیں رکھیں.اور کُرْسِیٌ علم کو بھی کہتے ہیں اور حکومت کو بھی (مفردات).اس لفظ کی اصل سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اس کے معنے جمع کر نے اور اکٹھا کر نے کے ہیں.اور چونکہ علم بھی پراگندہ معلومات کو جمع کر لیتا ہے اور حکومت ملک کے پراگندہ اجزاء کو جمع کر لیتی ہےاس لئے اسے بھی کرسی کہتے ہیں.تفسیر.ان آ یات میں پہلی بات جس کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے اللّٰہُ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ ہے یعنی اےانسان! خدا کو دیکھ کہ صرف وہی تیرا معبود ہے اس کے سوا اور کوئی تیرا معبود نہیں ہے.دنیا میں ہر ایک چیز کی قدر اس کی کم یا بی کی وجہ سے ہوتی ہے.مثلاً پا نی ایک بہت ضروری چیز ہے مگر لوگ اسے سنبھال کر نہیں رکھتے.کیو نکہ وہ جا نتے ہیں کہ جس وقت اس کی ضرورت پڑے گی اسی وقت مل جائےگا.ہوا صحت کے لئے کیسی ضروری چیز ہے مگر کو ئی انسان اس کو سنبھالتا نہیں کیو نکہ وہ جانتا ہے کہ جب اس کی ضرورت ہو گی
Page 439
عدل رکھا کہ اب وہ عدل پر زیادہ زور دینے لگے ہیں.اسی طرح پہلی آیت میںلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌاور دوسری میں لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ ہے.اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قبولیت اَخَذ سے اعلیٰ لفظ ہے اور اپنے اندر اعزاز کا ایک رنگ رکھتا ہے.جیسے کہتے ہیں بادشاہ نے فلاں چیز قبول کرلی.یہ کبھی نہیں کہتے کہ فقیر نے بادشاہ کی عطا کردہ چیز قبول کر لی لیکن اخذ میں یہ بات نہیں ہوتی.اخذ جس کے معنے لینا ہے ادنیٰ چیز اعلیٰ کے بدلہ میں لینے یا اعلیٰ چیز ادنیٰ کے بدلہ میں لینے یا ایک ہی جیسی قیمت رکھنے والی چیزیں ایک دوسرے سے لینے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب تک یہود کی اُمیدقائم تھی اور اُن کے عیوب گنائے نہیں گئے تھے.یہ فرمایا کہ اُن سے عدل نہیں لیا جائے گا.اور ’’لیا جائے گا‘‘ کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ خود لینے والا لے لے.اور اس طرح حساب پورا کر لے.لیکن لَا یُقْبَلُ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ دینے والا خود اصرار سے دیتا ہے لیکن پھر بھی نہیں لیا جاتا.اور یہ بات مایوسی کی حالت میں پیدا ہوتی ہے پس یہ تبدیلی بھی پند رھویں ۵۱ رکوع میں موقع کے لحاظ سے کی گئی ہے.اور بتایا گیا ہے کہ وہ تو مایوسی کی حالت میں چاہیں گے کہ معاوضہ لے لیا جائے مگر معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا.تیسری تبدیلی یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کے لئے لَا یُقْبَلُ آیا تھا اور کہا گیا تھا کہ لَا یُقْبَلُ مِنْھَا شَفَاعَۃٌ لیکن دوسری آیت میں لَا تَنْفَعُھَاشَفَاعَۃٌ آیا ہے.یہ تبدیلی بھی موقع کے لحاظ سے ضروری تھی.جب تک یہود کے عیوب بیان نہیں کئے گئے تھے وہ اُمید کر سکتے تھے کہ ہم انبیاء کی سفارش پیش کرینگے اور وہ قبول ہو جائیگی.اس خیال کے مناسب حال یہ جواب دیا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی لیکن بعد کے رکوعوں میں جب انبیاء کی مخالفتیں اور یہود کے دوسرے عیوب گِنائے گئے تو یہود کی یہ اُمید منقطع ہو گئی کہ ہم خود شفاعت پیش کر سکیں گے.لیکن یہ امید اب بھی ہو سکتی تھی کہ شاید انبیاء ہی رحم کر کے ہماری شفاعت کر دیں.اس لئے پندرھویں رکوع میں وَلَا تَنْفَعُھَا شَفَاعَۃٌکہا گیا.جس کے معنے یہ ہیں کہ سفارش کرنے والوں کی سفارش سے اور لوگ تو فائدہ اُٹھائیں گے مگر ان کے حق میں کوئی شفاعت کی ہی نہیں جائیگی کہ یہ اس سے فائدہ اُٹھاسکیں.لَا تَنْفَعُھَا سے یہ مراد نہیں کہ شفاعت تو ہو گی مگر مانی نہیں جائے گی بلکہ مراد یہ ہے کہ اُن کے حق میں کوئی از خود بھی شفاعت نہیں کریگا آخر شفاعت تو اِذْن سے ہوتی ہے بغیر اِذْ ن کے کون شفاعت کرسکتاہے.پس جب اِذْن نہ ہو گا تو شفاعت بھی نہیں ہو گی.اور جب شفاعت نہ ہو گی تو اس رحمت کے دروازے سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے.غرض یہ سب تبدیلیاں بالکل موقعہ کے مناسب ہیں اور قرآنی ترتیب کے کمال کی ایک زبردست شاہد ہیں.
Page 440
دکھاتا چلا جائےگا.کیونکہ وہ حَیيُّ و قَیُّوْمُ خدا ہے اور وہ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌکا مصداق ہے.اس پر اونگھ اور نیند ہی نہیں آ تی تو اس کے زندہ نشانات کا سلسلہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ جب ایسے خدا سے انسان اپنا تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اس کی ضرورتوں کا وہ آپ کفیل ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اس کی تا ئید کے لئے اپنے غیر معمولی نشا نات ظاہر کرتاہے.ہم نے دیکھا ہے حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کے پاس اکثر لوگ اپنی اما نتیں رکھواتے تھے اور آپ اس میں سے ضرورت پر خرچ کر تے رہتے تھے.آ پ فر ما یا کر تے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے اس طرح رزق دیتا رہتاہے بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ اما نت رکھوا نے والا آ پ کے پاس آتا اور کہتا کہ مجھے روپیہ کی ضرورت ہے.میری اما نت مجھے واپس دےدی جائے.آپ کی طبیعت بڑی سادہ تھی اور معمو لی سے معمولی کا غذ کو بھی آ پ ضا ئع کر نا پسند نہیں فر ماتے تھے.جب کسی نے مطا لبہ کر نا توآپ نے ردی سا کا غذ اٹھا نا اور اس پر اپنے گھروالوں کو لکھ د ینا کہ امانت میں سے دو سو روپیہ بھجو ا دیا جائے.اندر سے بعض دفعہ جوا ب آ تا کہ روپیہ تو خرچ ہو چکا ہے یا اتنے روپے ہیں اور اتنے رپوؤں کی کمی ہے.آپ نے اسے فر ما نا کہ ذرا ٹھہر جاؤ.ابھی روپیہ آ جاتا ہے.اتنے میں ہم نے دیکھنا کہ کوئی شخص دھو تی باندھے ہوئے جوناگڑھ یا بمبئی کا رہنے والا چلا آرہا ہے اور اس نے آ کر اتنا ہی روپیہ آپ کو پیش کر دینا.ایک دن تو لطیفہ ہوا کسی نے اپنا روپیہ ما نگا.اس دن آ پ کے پا س کو ئی روپیہ نہیں تھا مگر اسی وقت ایک شخص علاج کےلئے آ گیا.اور اس نے ایک پڑیہ میں کچھ رقم لپیٹ کر آ پ کے سامنے رکھ دی.حافظ روشن علی صا حبؓ کو علم تھا کہ روپیہ ما نگنے والا کتنا روپیہ مانگتا ہے.آ پ نے حافظ صا حبؓ سے فر ما یا دیکھو! اس میں کتنی رقم ہے؟ انہوں نے گنا تو کہنے لگے بس اتنی ہی رقم ہے جتنی رقم کی حضور کو ضرور ت تھی.آ پ نے فر ما یا یہ اس کو دے دو.اسی طرح آ پ ایک پرانے بزرگ کا وا قعہ سنا یا کر تے تھے کہ ایک دفعہ ایک قر ض خواہ ان کے پا س آ گیا.اور اس نے کہا کہ آپ نے میری اتنی رقم دینی ہے اور اس پر اتنا عرصہ گذر چکا ہے اب آپ میرا روپیہ ادا کر دیں.انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ہے نہیں جب آئےگا دے دوںگا.وہ کہنے لگا.تم بڑے بزرگ بنے پھرتے ہو اور قر ض لے کر ادا نہیں کرتے یہ کہاں کی شرافت ہے.اتنے میں وہاں ایک حلوہ بیچنے والا لڑکا آ گیا.انہوں نے اس سے کہا کہ آ ٹھ آنے کا حلوہ دےدو.لڑکے نے حلوہ دےدیا اور انہوں نے وہ حلوہ اس قارض کو کھلا دیا.لڑکا کہنے لگا کہ میرے پیسے میرے حوالے کیجئیے.وہ کہنے لگے تم آ ٹھ آ نے مانگتے ہو اور میر ے پاس تو دو آ نے بھی نہیں.وہ لڑکا شور مچا نے لگ گیا.یہ
Page 441
دیکھ کر وہ قرض خواہ کہنے لگا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میری رقم تو ماری ہی تھی اس غریب کی اٹھنّی بھی ہضم کر لی.غرض وہ دونوں شور مچا تے رہے اور وہ بزرگ اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھے رہے.اتنے میں ایک شخص آ یا اور اس نے اپنی جیب میں سے ایک پڑیہ نکال کر انہیں پیش کی.اور کہا کہ فلاں امیر نے آ پ کو نذرانہ بھیجا ہے.انہوں نے اسے کھو لا تو اس میں روپے تو اتنے ہی تھے جتنے قر ض خواہ ما نگتا تھا مگر اس میں اٹھنّی نہیں تھی.کہنے لگے.یہ میری پڑ یہ نہیں اسے واپس لے جاؤ.یہ سنتے ہی اس کا رنگ فق ہو گیا.اور اس نے جھٹ اپنی جیب سے ایک دوسری پڑ یہ نکالی اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے.آ پ کی پڑ یہ یہ ہے.انہوں نے اسے کھو لا.تو اس میں اتنے ہی روپے تھے جو قار ض ما نگ رہا تھا اور ایک اٹھنی بھی تھی.انہوں نے دونوں کو بلا یا.اور وہ روپے انہیں دے دئیے.غر ض زندہ خدا اپنے بندوں کی تائید میں ہمیشہ اپنے نشا نات دکھا تا رہتا ہے.پھر وہ اَلْقَيُّوْمُ ہے.کو ئی کہہ سکتا ہے کہ اب تو میرا یہ آ قا ہے لیکن پہلے میں فلاں کے پاس ملازم رہ چکا ہوں.اس لئے اس کا بھی مجھ پر احسان ہے اور میرے لئے اس کی قدر کرنا بھی ضروری ہے.خدا تعالیٰ فر ما تا ہے کہ میں تمہارا آج خدا نہیں بنا بلکہ ہمیشہ سے خدا ہوں.تم پر کسی کا پچھلا احسان نہیں ہے.میں وہ خدا ہوں جو ہمیشہ قا ئم رہنے والا اور تمہیں قا ئم رکھنے والا ہوں.اس لئے تم پر میرا ہی احسان ہے کسی اور کا احسان نہیں.پھر فر ماتا ہے لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ممکن ہے کو ئی کہے کہ مان لیا خدا ایک ہی ہے اس کے سوا اور کوئی نہیں.وہ ہمیشہ زندہ ہے.اور وہی ہمارا پہلے آ قا تھا اور وہی اب بھی ہے.مگر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ خدا کو نیند آ ئے اور وہ سو جائے.اور اس وقت اس کی جگہ اس کے درباری کام کریں.اس لئے انہیں بھی خو ش رکھنا چاہیے اور ان کی بھی خوشامد کر نی چا ہیے.اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے.تمہارا وہ اللہ ہے کہ اس کو کبھی اونگھ اور نیند نہیں آ تی تم اس کو دنیوی با دشا ہوں اور حا کموں کی طر ح نہ سمجھو.جہاں تمہیں درباریوں کی خو شامد کر نی پڑتی ہے.تمہارا خدا ایسا نہیں کہ کبھی اسے اونگھ آئے یا وہ سو جائے.وہ ہر وقت جا گتاہے اور ہر ایک بات کا خود نگران ہے.اس میںاللہ تعالیٰ نے کیا ہی لطیف بات بیان فر مائی ہے فر ما تا ہے.لَا تَاْ خُذُہٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوْمٌ کہ اس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند.تر تیب کلام کا یہ قا عدہ ہے کہ پہلے چھو ٹی باتو ں کا ذکر ہو تا ہے.پھر بڑی بات کا.اگر اس کے خلاف کیا جائے تو کلام غلط ہو جاتا ہے.مثلاً یہ تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سخت بیمار نہیں تھا بلکہ وہ تو کچھ بھی بیمار نہ تھا.لیکن اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص کچھ بیمار نہیں تھا بلکہ وہ تو زیادہ بیمار بھی نہ تھا تو فقرہ غلط ہو جاتا ہے.کیو نکہ پہلے بڑا اور پھر چھو ٹا درجہ بیان کیا جاتا ہے.مگر یہاںاللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ نہ اسے اونگھ آ تی ہے اور نہ نیند.حالا نکہ جب اونگھ کی نفی کر دی
Page 442
گئی تھی تو نیند کی خود ہی نفی ہو جاتی ہے.پھر نیند کی نفی کی کیا ضرورت تھی؟ سو یاد رکھنا چا ہیے کہ اس میں ایک حکمت ہے.اور وہ یہ کہ سِنَۃٌ اس کو کہتے ہیں کہ جب سخت نیند کی وجہ سے انسان کی آ نکھیں بند ہو جائیں.چنا نچہ جب انسان کو بہت زیادہ نیند آ ئی ہو ئی ہو اس وقت اونگھ آتی ہے.اور جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو اونگھ نہیں آ تی.تو فر ما یا کہ خدا تعالیٰ کو کبھی اونگھ نہیں آ تی کہ کام کرنےکی وجہ سے وہ تھک گیا ہو.اور اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ اس کی آ نکھیں بند ہو گئی ہوں اور نہ اسے معمولی نیند آ تی ہے.غر ض تر تیب بیان کے لحا ظ سے سِنَۃٌ کا ہی پہلے ذکر آ نا ضروری تھا.اور نوم کا بعد میں.پھر فر ما یا.لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ تمہارا آ قا ایسا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے.ایسی صورت میں تم اس کے مقا بلہ میں کسی اور کو اپنا آ قا کس طر ح بنا سکتے ہو؟پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت تو نہیں کر تے ہاں دوسروں کونیازیں دیتے اور ان سے مرادیں ما نگتے ہیں کیو نکہ وہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے.خدا تعالیٰ فر ما تا ہےمَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.ہمارے حکم کے بغیر تو کو ئی شفا عت ہی نہیں کر سکتا.پس تمہاری یہ امید بھی غلط ہے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑ ھ کر اور کو ن ہے؟لیکن حضرت مسیح مو عودعلیہ السلام نے ایک دفعہ جب نواب محمد علی خان صاحبؓ کے لڑ کے عبد الر حیم خان کےلئے جبکہ وہ شد ید بیمار تھا دُعا کی تو الہام ہوا کہ ’’ تقدیر مبرم ہے اور ہلا کت مقدر.‘‘ آ پ کو خیال آ یا کہ نواب صا حب سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قا دیان آ رہے ہیں.ان کا لڑ کا فوت ہو گیا تو انہیں ابتلاء نہ آ جا ئے.اس لئے آ پ نے خدا تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ الٰہی میں اس لڑ کے کی صحت کے لئے شفا عت کر تا ہوں.اس پر آپ کو بڑے زور سے الہا م ہوا مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ یعنی تم کو ن ہو جو میری اجا زت کے بغیر شفا عت کر تے ہو؟ اب دیکھو حضرت مسیح مو عو دعلیہ الصلوۃو السلام کتنے بڑے انسان تھے!تیرہ سو سال سے دنیا آ پ کی منتظر تھی.مگر وہ بھی سفارش کر تا ہے تواللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ تم کو ن ہو کہ بلا اجا زت سفارش کرو؟ حضرت مسیح مو عودعلیہ الصلوۃو السلام فر ما یا کر تے تھے کہ جب مجھے یہ الہا م ہوا.تو میں گر پڑا اور بدن پر رعشہ طا ری ہو گیا اور قر یب تھا کہ میری جان نکل جا تی.لیکن جب یہ حا لت ہو ئی تو اللہ تعالیٰ نے فر ما یا.اِنَّکَ اَنْتَ الْمَجَازُ.اچھا.اب ہم شفا عت کی اجازت دیتے ہیں.چنا نچہ آپ نے شفاعت کی.اور عبد الرحیم خان اچھے ہو گئے.(الہام مؤرخہ ۲۵؍ اکتوبر ۱۹۰۳ء) غر ض جب مسیح موعودعلیہ السلام جیسے انسان کو........اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کون ہو جو بلا اذن سفارش کرو تو اور لو گوں کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کی سفارش کر سکیں؟
Page 443
حد یثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیا مت کے دن آ نحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اِذن ہو گا تب آ پ سفا رش کریں گے(ترمذی کتاب صفة القیامة باب ما جاء فی الشفاعة) پھر کیسا نا دان ہے وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ فلاں میری سفا رش کر دےگا! پھر ایک اور بات رہ جا تی ہے اور وہ یہ کہ کو ئی کہہ سکتا ہے کہ مانا شفا عت بلا اجا زت نہیں ہو سکتی.لیکن با دشاہ کے جس طر ح درباری ہو تے ہیں اور ان کے ذریعہ بادشاہ تک رسا ئی حاصل کر کے فا ئدہ اٹھا یا جا تاہے.اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی درباری ہو نے چا ہئیں.اللہ تعالیٰ فرما تا ہے.ان احمقوں کواتنا بھی پتہ نہیں کہ دنیا کے با دشاہ کیوں درباری رکھتے ہیں.وہ تو اس لئے رکھتے ہیں کہ انہیں ان سے حا لات معلوم کر نے کی ضرورت ہو تی ہے کیو نکہ با دشا ہ نہیں جا نتا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہاری اگلی پچھلی سا ری با تیں جا نتا ہے.پھر اس کو درباری رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یَعْلَمُ مَابَیْنَ اَیْدِیْھِمْ وَ مَا خَلْفَھُمْ کے دو معنے ہیں.ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جا نتا ہے جو آ گے ہو نا ہے اور اسے بھی جا نتا ہے جو لوگ پیچھے کر چکے ہیں.دوسرے معنے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا موں کو بھی جا نتا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور ان کا موں کو بھی جا نتا ہے جو انہیں کر نے چا ہیے تھے.لیکن انہوں نے ترک کر دئیے.پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ درباری رکھے؟ وَ لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ.پھر اس کے علوم کا کو ئی شخص احا طہ نہیں کر سکتا کسی کو اس کی حقیقت اپنی کو شش سے معلوم نہیں ہو سکتی.ہاں! جس کو وہ آپ ہی بتا دے اور جس قدر بتا دے وہ اتنا ہی جا نتا ہے اس سے زیادہ نہیں.اس آ یت میں خدا تعالیٰ نے صاف طورپر بتا دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم کا کو ئی احا طہ نہیں کر سکتا.نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کوئی اور شخص.بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم تمام نبیوں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کےبڑے محبوب ہیں بلکہ آ پ کی اتباع کرنےوالا بھی خدا تعالیٰ کا محبوب ہو جا تا ہے مگر با و جود اس کے آ پ خدا تعالیٰ کی مخلوق اور اسی کے محتاج تھے.پس آ پ کے اندر وہی صفات رہیں گی جو بندوں میں ہو تی ہیں اور وہ صفات کبھی نہیں آ سکتیں جو خدا نے صرف اپنے لئے مخصوص کی ہو ئی ہیں.لَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ میں اس امر کی طر ف بھی تو جہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں اتنی غیر محدود ہیں کہ انہیں کلی طور پر طے کر نےکا کو ئی انسان خیال بھی نہیں کر سکتا.جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑ ھتا ہے اور وہ اپنے مقام کے مطا بق اس کے انوار و بر کات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے تواللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر اپنی دوسری تجلّی ظاہر کرتا ہے اور جب وہ دوسری تجلّی کو بھی برداشت کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا
Page 444
ہے کہ اب یہ تیسری تجلّی کے قا بل ہو گیا ہے.تو اس پر اپنی تیسری تجلّی ظاہر کر تا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے قر ب میں بڑھتا چلا جا تا ہے.رسول کر یم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے اس کیفیت کو ایک نہا یت ہی لطیف مثال کے سا تھ وا ضح فر ما یا ہے.آپ فر ما تے ہیں کہ جو شخص دوزخ میں سب سے پیچھے رہ جا ئےگا.اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ ما نگو مجھ سے کیا ما نگتے ہو وہ کہے گا بس یہی ما نگتا ہوں کہ مجھے دوزخ سے نکال دیا جائے.اللہ تعالیٰ فر مائےگا کہ اچھا.اور وہ اسے دوزخ سے نکال لے گا.جس سے اسے بہت خوشی ہو گی لیکن کچھ روز کے بعد اسے دور ایک سر سبز و شا داب درخت نظر آئےگا اور اس کے دل میں لا لچ پیدا ہو گا کہ اگر میں وہاں پہنچ کر اس کے نیچے بیٹھ سکوں تو کیا اچھا ہو.کچھ مدت تک تو وہ اس خیال کے اظہار سے رکے گا.مگر آ خرخدا تعالیٰ سے کہے گا کہ ہے تو بڑی بات لیکن اگر آ پ مجھ پر رحم کر کے اس درخت کے نیچے بیٹھنے دیں تو بہت مہر بانی ہو گی.اللہ تعالیٰ اس کی بات کو مان لےگا اور اس درخت کے نیچے اسے پہنچا دےگا.آخر جب وہ اس درخت کے نیچے کچھ عرصہ تک راحت حاصل کر لے گا تو پھراللہ تعالیٰ امتحان کے لئے اس سے بہتر درخت اس سے کچھ فاصلے پر ظاہرکرے گا.اور پھر وہ لا لچ کر ے گا کہ وہ اس کے نیچے بیٹھے کچھ مدت تک تو وہ اپنے نفس کی اس خواہش کو بر داشت کر ے گا اور کہے گا کہ میں اب اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کس طرح کروں؟لیکن آ خر وہ درخواست کر ہی دےگا اور کہے گا کہ آئندہ اور کچھ نہ مانگوںگا.تب خدا تعالیٰ اسے وہاں لے جائےگا.اورپھر وہ دور سے جنت کا دروازہ دیکھے گا اور آ خر اس سے با ہر رہنا برداشت نہیں کرےگا.اور خدا تعالیٰ سے کہےگا کہ مجھے اس جنت کے دروازہ کے آ گے تو بٹھا دے میں اندر جانے کی درخواست نہیں کر تا.صرف با ہر بیٹھا دے وہیں سے لطف حاصل کر لو ںگا.اللہ تعالی اس سے پو چھے گا کیا تو اس کے بعد تو کچھ نہیں ما نگے گا.بندہ کہےگا نہیں اس پراللہ تعالیٰ اُسے جنت کے دروازے پر بٹھا دے گا لیکن وہاں اسے کس طر ح چین حاصل ہو سکتا ہے آ خر وہ بے تاب ہو کر کہےگا کہ یا اللہ مجھے دروازہ کے اندر کی طرف بٹھا دے.میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے جنت کی نعماء دے.میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دروازہ کے اندر بٹھا دے اس پراللہ تعالیٰ ہنسے گا اور کہےگا کہ میرے بندہ کی حرص کہیں ختم نہیں ہوتی.جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چا ہو رہو.(مشکٰوة کتاب احوال القیامۃ و بدء الخلق باب الحوض و الشفاعۃ) غرضیکہ پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی تجلّی دکھاتا ہے اور اسے دیکھ کر جب ملائکہ صفت انسان بے تاب ہو جاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ خدایا !تو مجھے کا مل تجلی دکھا تو پھراللہ تعالیٰ اسے دوسرے مقام کی پہلے ہلکی سی تجلی دکھا تا ہے اور پھر پوری تجلی اور یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے.بہر حال اللہ تعالیٰ کی ہستی غیر محدود ہے اور کوئی شخص اس کا احا طہ
Page 445
نہیں کر سکتا.پھر فر ما تا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ.اللہ تعالیٰ کا علم آ سمان اور زمین کو گھیر ے ہوئے ہے.یعنی اسے ہر چیز کا انتہا ئی علم ہے اورکوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے علم سے با ہر ہو.انسانی علم با لکل محدود ہو تا ہے.بعض اوقات وہ ایک چیز کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھی ہے لیکن اس کا نتیجہ خراب ہوتا ہے جیسے حضرت مسیح مو عود علیہ الصلوةوالسلام کو میر عباس علی لدھیا نوی کے متعلق ایک وقت علم دیا گیا کہ وہ نیک ہے تو آ پ اس کی تعریف فرمانے لگے مگر چونکہ اس وقت آپ کو اس کے انجام کا علم نہیں تھا اس لئے آپ کو پتہ نہ لگا کہ ایک دن وہ مر تد ہوجائےگا.لیکن بعد میںاللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دے دیا.غرض انسانی علم بہت ہی محدود ہے صرف خدا تعالیٰ ہی کا مل علم رکھتا ہے جو سب پر حا وی ہے اور کو ئی شخص اس کے علوم کا احا طہ نہیں کر سکتا.پھر وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ میں سا ئینس کے اس عظیم الشان نکتہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ کائنات عالم کی لمبا ئی کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کو ئی نہیں جا نتا.اس زما نہ میں جس حد تک علم ہیئت میں تر قی ہو چکی ہے.اتنی پہلے کبھی نہیں ہو ئی.آ ج دنیا کی لمبا ئی کا اندازہ میلوں میں نہیں لگا یا جاتا.مثلاً یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک زمین سے دوسری زمین تک اتنے میل کا فا صلہ ہے بلکہ اس لمبائی کا اندازہ روشنی کی رفتار سے لگا یا جا تا ہے.روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ اسی ہزار میل چلتی ہے اور دنیا کی وسعت کا اندازہ اس نور کی روشنی سے لگا تے ہیں.گویا یہ بھی اَللّٰہُ نُوْرُالسَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ(النور: ۳۶) کی صدا قت کا ثبوت ہے کیو نکہ اس آ یت میں بتا یا گیا تھا کہ زمین و آ سمان کی وسعت کا اندازہ تم کسی چیز سے نہیں لگا سکتے صرف نور اور اس کی رفتار سے ہی لگا سکتے ہو.غرض جب ایک سیکنڈ میں روشنی ایک لاکھ اسّی ہزار میل چلتی ہے.تو ایک منٹ میںایک کروڑ آ ٹھ لاکھ میل چلے گی.پھر اسے ایک گھنٹہ کے ساتھ ضرب دو تو یہ ۶۴ کروڑ ۸۰ لاکھ میل بنتے ہیں.ان میلوں کو ایک دن کی روشنی کا حساب لگا نے کے لئے ۲۴ سے ضرب دیں تو یہ ۱۵ ارب ۵۵ کروڑ ۲۰ لاکھ میل رفتار بن جاتی ہے.اب پھر ایک سال کی رفتار کا حساب لگا نے کے لئے ۳۶۰ دنوں سے ضرب دیں تو ۵۵ کھرب ۷۶ ارب ۷۲ کروڑ میل بنتے ہیں.یہ حساب صرف روشنی کے ایک سال کی لمبا ئی کا ہو تا ہے.لیکن دنیا کی لمبا ئی علم ہیئت والے روشنی کے تین ہزار سال قراد دیتے تھے.پس ان اعداد کو تین ہزار سال سے ضرب دینی ہو گی.اب اس کا حاصل ضرب جو نکلے وہ حسا بی لحاظ سے در حقیقت نا قا بلِ اندازہ ہی ہو جا تا ہے.کیو نکہ اربوں کے اوپر کا حساب در حقیقت حساب ہی نہیں سمجھا جا تا مگر یہ حساب یہیں ختم نہیں ہو گیا.جوں جوں نئے آ لات دریا فت ہو رہے ہیںیہ اندازے بھی غلط ثا بت ہو رہے ہیں.پہلی جنگ عظیم کے بعد
Page 446
یہ قرار دیا گیا کہ دنیا کی لمبائی روشنی کے چھ ہزار سال کے برابر ہے.مگر اس کے بعد تحقیق ہو ئی کہ یہ سب باتیں غلط ہیں.ہم دنیا کی لمبائی کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کیو نکہ جس طر ح بچہ کا قد بڑ ھتا ہے اسی طرح دنیا بھی بڑھتی چلی جارہی ہے.اور اب اس کی لمبا ئی روشنی کے بارہ ہزار سالوں کے برابر سمجھی جا تی ہے.اس کی طر ف قرآ ن کریم کی اس آ یت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ( الز مر:۶۸) یعنی سب کی سب زمین اس کی مملو کہ ہے.اور آ سمان اور زمین دونوں قیامت کے دن اس کے دائیں ہا تھ میں لپٹے ہو ئے ہو ںگے.اور جوچیز خدا کی مٹھی میں ہواس کا اندازہ انسان کہاں لگا سکتا ہے ؟یہی وجہ ہے کہ جب انسان کا علم اندازے کے قریب قریب پہنچنے لگتا ہے تو خدا تعالیٰ کائنات کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے.غرض اس نئے علم سے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ کی صداقت کا سا ئینس نے اقرار کر لیا ہے.اور دنیا اس حقیقت کو تسلیم کر چکی ہے کہ زمین و آ سمان کی وسعت کا اندازہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کو ئی نہیںکر سکتا.وَ لَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا.پھر کو ئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا علم حا صل کر نے کے لئے تو اپنے درباری مقرر نہیں کئے لیکن کام کرنے کے لئے کچھ مددگار تو ضرور مقررکئے ہو ںگے تا کہ وہ اس کا ہاتھ بٹا ئیں.فر ما یا اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں.وہ سب کام خود کر رہا ہے اور ا للہ تعالیٰ کی طا قت ایسی وسیع ہے کہ کو ئی چیز اس کے قبضہ سے باہر نہیں.اور نہ کسی چیز کا انتظام اس کو تھکا سکتا ہے.اب ایک ہی اعتراض رہ جاتا ہے.اور وہ یہ کہ مانا خدا کو علم کے لئے اور مدد کے لئے کسی کی ضرورت نہیں مگر شان و شو کت بھی تو کوئی چیز ہے اس کے اظہار کےلئے ہی اس نے درباری مقرر کئے ہوںگے.اس اعتراض کو وَ ھُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُکہہ کر ردّ فر ما دیا.یعنی وہ بہت بڑا ہے اور کو ئی چیز نہیں جو اس کے سا تھ مل کر اس کے رتبہ کو بڑھا سکے.جو چیز خدا کے ساتھ ملے گی اس کا اپنا ہی رتبہ بڑھے گانہ کہ خدا کا.پس یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت کے لئے درباری مقرر کئے ہو ںگے ٹھیک نہیں.وہ بہت بلند اور بڑی شان رکھنے والا ہے.عَلِیٌّ میں اس کی رفعت اور بلندی کی طر ف اور عَظِیْمٌ میں اس کی طا قتوں کی وسعت کی طرف اشارہ کیا ہے.یہ وہ خدا ہے جو اسلام پیش کر تا ہے.اگر ایسے خدا کے ہوتے ہوئے کو ئی کسی اور طرف جائے تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے اگر کسی شخص کو نہایت عمدہ کھا نا ملے اور وہ اسے چھوڑ کر نجا ست کی طرف دوڑے.اگر کسی شخص کو عمدہ کپڑا ملے اور وہ اسے چھوڑ کر میلی کچیلی لنگو ٹی باندھ لے تو بتاؤ کیا وہ دانا اور عقلمند کہلا نے کے قابل ہو گا؟ نہیں اور ہر گز نہیں.دانا وہی ہے جو بہتر چیز کو پسند کرے.پس ا للہ تعالیٰ سےبہتر اور کو ئی نہیں.
Page 447
َاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ١ۙ۫ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ١ۚ فَمَنْ دین کے معاملہ میں کسی قسم کا جبر (جائز) نہیں.(کیونکہ )ہدایت اور گمراہی کا (باہمی )فرق خوب ظاہر ہو چکا ہے.يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ پس( سمجھ لو کہ) جو شخص (اپنی مرضی سے )نیکی سے روکنے والے(کی بات ماننے) سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ١ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا١ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۰۰۲۵۷ رکھے تو اس نے (ایک)نہایت مضبوط قابل اعتماد چیز کو جو (کبھی) ٹوٹنے کی نہیں مضبوطی سے پکڑ لیا.اور اللہ بہت سننے والا (اور) بہت جاننے والا ہے.حلّ لُغات.رُشْدٌ رشد کے معنے ہیں صداقت پر استقلال سے قائم رہنا نیز یہ غَیٌّ کے اضداد میں سے ہے.(اقرب) اَلْغَیُّ کے معنے ہیں اَلضَّلٰلَۃُ.گمراہی.اَلْھَلَٓا کَۃُ.تباہی.اَلْخَیْبَۃُ: ناکا می.( اقرب) اَلطَّا غُوْتُ طَغٰی سے نکلا ہے جس کے معنے ہر ایسی چیز کے ہیں جو حد سے نکل جا ئے.اور سر کش ہو جائے طاغوت کے ان معنوں میں شیطان بھی شا مل ہے کیو نکہ وہ انسا ن کو سر کشی کی طرف لے جا تا ہے اور اس میں وہ انسان بھی شا مل ہیں جو لو گوں کو خدا تعالیٰ سے دور کر تے ہیں.(اقرب) اِسْتِمْسَاکٌ کے معنےپکڑنے کے ہیں.(اقرب) اَلْعُرْ وَۃُ اَلْعُرْوَۃُ مِنَ الدَّ لْوِ وَ الْکُوْزِ الْمِقْبَضُ اَیْ اُذُ نُھُمَا.یعنی عُروہ ڈول یا لو ٹے کے دستہ کو کہتے ہیں جس سے اسے پکڑا جا تا ہے.اسی طرح عروہ کے معنے مَا یُوْ ثَقُ بِہٖ کے بھی ہیں.یعنی ایسی چیز جس پر اعتبار کیا جائے.گویا ہر ایسی چیز جس پر سہارا لیا جائے یا جس پر اعتماد کیا جا سکے وہ عُروہ کہلاتی ہے.اسی طرح عُروہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو کبھی ضا ئع نہ ہو نے والی ہو چنا نچہ عُروہؔ اس گھاس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہرا ر ہے اور عروہ کے معنے اَلنَّفِیْسُ مِنَ الْمَا لِ کے بھی ہیں.یعنی اچھا اور بہتر ین مال.(اقرب) تفسیر.یہ عجیب بات ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض کیا جا تا ہے کہ وہ جبر سے دین پھیلا نے کی تعلیم دیتا ہے
Page 448
حالا نکہ اسلام اگر ایک طرف جہاد کے لئے مسلما نوں کو تیار کر تا ہے جیسا کہ اس سورۃ میں وہ فر ما چکا ہے کہ وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ (البقرۃ: ۱۹۱) یعنی تم ا للہ تعالیٰ کی راہ میں ان لو گوں سے جنگ کر و جو تم سے جنگ کر تے ہیں.تو دوسری طرف وہ یہ بھی فر ما تا ہے کہ لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ.یعنی جنگ کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چا ہیے کہ لو گو ں کو مسلمان بنا نے کے لئے جبر کر نا جا ئز ہو گیا ہے بلکہ جنگ کا یہ حکم محض دشمن کے شر سے بچنے اور اس کے مفا سد کو دور کر نے کے لئے دیا گیا ہے.اگر اسلا م میں جبر جا ئز ہو تا تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم ایک طر ف تو مسلما نوں کو لڑا ئی کا حکم دیتا اور دوسری طر ف اسی سورۃ میں یہ فر ما دیتا کہ دین کے لئے جبر نہ کرو.کیا اس کا وا ضح الفا ظ میں یہ مطلب نہیں کہ اسلام دین کے معا ملہ میں دوسروں پر جبر کر نا کسی صورت میں بھی جا ئز قرار نہیں دیتا؟ پس یہ آ یت دین کے معا ملہ میں ہر قسم کے جبر کو نہ صرف نا جا ئز قرار دیتی ہے بلکہ جس مقام پر یہ آیت وا قع ہے اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جبر کے با لکل خلاف ہے.پس عیسا ئی مستشر قین کا یہ اعتراض با لکل غلط ہے کہ اسلا م تلوار کے ذریعہ غیر مذ اہب والوں کو اسلام میں داخل کر نے کا حکم دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ سب سے پہلا مذہب ہے جس نے دنیا کے سا منے یہ تعلیم پیش کی کہ مذہب کے معاملہ میں ہر شخص کو آ زادی حا صل ہے اور دین کے بارہ میں کسی پر کوئی جبر نہیں.قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ یہ جملہ مستا نفہ ہے یعنی اس سے پہلے ایک جملہ مقدر ہے جس کا یہ جوا ب دیا گیا ہے.چو نکہ ا للہ تعالیٰ نے یہ فر ما یا تھا کہ دین کے لئے جبر جائز نہیں.اس لئے سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب دین ایک اعلیٰ درجہ کی چیز ہے تو کیوں اس کے لئے لو گوں پر جبر نہ کیا جائے.اور انہیں بزور اس نعمت سے متمتع نہ کیا جائے؟ا للہ تعالیٰ اس سوال کے جواب میں فر ما تا ہے جب گمراہی اور ہدایت ظا ہر ہو گئی ہے تو اب جبر کی ضرورت نہیں.صرف ہدایت کا پیش کردینا تمہارا کام ہے.کیو نکہ جو حق بات تھی وہ گمراہی اور ضلالت کے با لمقا بل پورے طور پر ظا ہر ہو گئی ہے.غرض اس آیت میں خدا تعالیٰ نے وجہ بیان فر مائی ہے کہ کیوں اسلام کو جبر کی ضرورت نہیں.فر ما تا ہے.جبر اس وقت ہو تا ہے.جب کو ئی بات دلیل سے ثا بت نہ ہو سکے.یا جس کو سمجھا یا جائے.وہ سمجھنے کے قا بل نہ ہو.مثلاً ایک بچہ کی عقل چو نکہ کمزور ہوتی ہے.اس لئے بسا اوقات اس کی مر ضی کے خلا ف اور جبر کر نےوالے کی مر ضی کے موا فق کام کر نے پر مجبور کیا جاتا ہے.لیکن اس بچہ میں جب عقل آ جا تی ہے تو پھر وہ اپنے آ پ ہی سمجھ جاتا ہے اور اپنے نفع اور نقصان کو سوچ سکتا ہے.اس حالت میں اس پر کو ئی جبر نہیں کر تا.اسلام کے متعلق ا للہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ اس میں ہر قسم کے دلائل کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے.اس لئے اسے منوانے کے لئے کسی پر جبر کر نے کی ضرورت نہیں.بلکہ
Page 449
وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ اَمْنًا١ؕ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے اس گھر (یعنی کعبہ) کو لوگوں کے لئے باربار جمع ہونےکی جگہ اور امن (کا وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى١ؕ وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى مقام)بنایا تھا اور (حکم دیا تھا کہ) ابراہیم ؑ کے کھڑےہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنائو اور اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآىِٕفِيْنَ ہم نے ابراہیم ؑ اور اسماعیل ؑ کوتاکیدی حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ۰۰۱۲۶ اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجد ہ کرنے والوں کے لئے پاک (اور صاف) رکھو.حَلّ لُغَات.مَثَا بَۃٌ کے معنے ہیں مُجْتَمَعُ النَّاسِ بَعْدَ تَفَرُّقِھِمْ وہ جگہ جہاں متفرق ہونے کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں.(اقرب) مفردات راغب میں لکھا ہے.اَلْمَثَا بَۃُ: اَلْمَکَانُ الَّذِیْ یُکْتَبُ فِیْہِ الثَّوَابُ.مثابہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آنے کی وجہ سے انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے.وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً میں مَثَا بَۃً کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں.اوّل یہ مفعول ثانی ہے اور جَعَلَ بمعنے صَیَّرَ ہے.اس لحاظ سے اِس کے معنے یہ ہیں کہ صَیَّرْنَا الْبَیْتَ مَثَا بَۃً ہم نے خانہ کعبہ کو مثابہ بنایا ہے.دوسرے مَثَا بَۃً حال بھی ہو سکتا ہے یعنی جَعَلْنَا اْلبَیْتَ حَالَ کَوْنِہٖ مَثَا بَۃً لِّلنَّاسِ.اس صورت میں جَعَلَ بمعنے صَیَّرَ نہیں بلکہ بنانے کے ہوںگے اور مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے خانہ کعبہ ایسے حال میں بنایا ہے کہ وہ اپنے اندر مثابہ کی خصوصیات رکھتا تھا.اَ مْنٌ کے معنے ہوتے ہیں.(۱) اطمینان قلب (۲) سَلَامَۃٌ مِّنَ الْخَوْفِ.دل کا اطمینان اور ظاہری خطرات سے نجات.جب انسان ظاہری خطرات سے بھی محفوظ ہو اور اس کے دل کو بھی اطمینان حاصل ہو تو یہ کامل امن ہوتا ہے.مِنْ کے کئی معنے ہیں.مگر اس جگہ یہ تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے اور زائدہ بھی.زائد ہ کے یہ معنے نہیں کہ وہ زائد ہے اور کوئی معنے نہیں دیتا بلکہ یہ عربی زبان کی ایک اصلاح ہے جو زور دینے کے لئے استعمال کی جاتی ہے.ایسا مِنْ
Page 450
بتا تی ہیں کہ مذ ہبی جنگیں تبھی جا ئز ہیں جبکہ کو ئی قوم رَبُّنَا اللّٰہَ کہنے سے روکے.یعنی دین میں دخل دے اور چا ہے کہ دوسری اقوام کے معا بد گرائے جائیں اور ان سے ان کا مذ ہب چھڑوایا جائے یا ان کو قتل کیا جائے.ایسی صور ت میں اسلام اس قوم سے جنگ کی اجا زت دیتا ہے.کیو نکہ اسلام دنیا میں بطور شا ہد اور محا فظ کے آ یا ہے نہ کہ بطور جا بر اور ظا لم کے.فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چا ہیے کہ کفر کے معنے صرف انکار کر نے کے ہو تے ہیں خواہ وہ کسی چیز کا انکار ہو.قرآ ن کریم میں یہ لفظ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے اور بُرے معنوں میں بھی.اس جگہ یہ لفظ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے.اوراللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ جو لوگ شیطا نوں اور شیطا نی لو گوں کی باتیں ما ننے سے قطعی طو ر پر انکار کر دیتے ہیں اوراللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لے آ تے ہیں وہ ایک مضبوط چٹان پر قا ئم ہو جاتے ہیں.لیکن اس کے مقا بلہ میں قرآ ن کریم میں یَکْفُرُوْنَ بِا للّٰہِ (النسا ء: ۱۵۱) بھی آ تا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کر تے ہیں.پس جہاں تک اس لفظ کے ظاہر کا تعلق ہے.یہ نہ بُرا ہے نہ اچھا ہے.اصل معنے تو اس کے ڈھا نپ دینے کے ہو تے ہیں.بدی کا ڈھا نپنا بھی کفر کہلائےگا اور نیکی کا ڈھا نپنا بھی کفر کہلا ئےگا.بدی کا چھپا نا بھی کفر کہلا ئےگا اور نیکی کا چھپا نا بھی کفر کہلا ئےگا.لیکن چو نکہ کثرت سے قر آ ن کریم میں یہ لفظ نیکی کے انکار کے متعلق استعمال ہوا ہے اس لئے جب کسی قر ینہ کے بغیر یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے بُرے ہی کئے جاتے ہیں.جس طرح مومن کے معنے بھی ایسے ہی ہیں لیکن وہ زیادہ تر نیکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.اس لئے جب مومن کا لفظ بغیر کسی قرینہ کے استعمال ہو تو اس کے معنے ہمیشہ نیک کے ہی کئے جا ئیں گے حا لانکہ قر آن کریم میں مومن کا لفظ بھی بر ے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ فر ما تاہے.یُؤْ مِنُوْنَ بِا لْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ.(النسا ء: ۵۲) وہ بےفائدہ با توں اور حد سے بڑھنے والوں پر ایمان رکھتے ہیں.اس جگہ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ میں طا غوت کا کفر کر نے سے اس کی ذات کا انکار مراد نہیں بلکہ یہ مرا دہے کہ اس کی بات نہ ما نے.اس کے مقا بلہ میںاللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ رکھا ہے جس کے معنے خدا تعالیٰ کی بات ما ننے کے ہیں اور فر ما یا ہے کہ جو شخص طا غوت کا انکار کر تا ہے.اوراللہ تعالیٰ پر ایمان لا تا ہے وہ ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں.اگر انکار کے معنے کسی شے کی ذات کے انکار کے لئے جائیں تو اس آ یت کے یہ معنے ہوںگے کہ ہلا کت سے وہی شخص بچتا ہے جو شیطان کے وجود کا انکار کرے اوراللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے حالانکہ یہ معنے سرا سر غلط ہیں.کیو نکہ قر آ ن کریم صاف طور پر خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی اقرار کر تا ہے اور شیطان کے وجود کا بھی اقرار کر تا ہے.پس اقرار اور ایمان سے اس آیت
Page 451
میں یہی مراد ہے کہ وہ شیطان کی با توں کو ردّ کر تا اور خدا تعالیٰ کی با توں کو ما نتا ہے.ایسے شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى.عروہ کے معنے دستہ کے بھی ہو تے ہیں جس سے کسی چیز کو پکڑا جاتا ہے اور عُروہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس پر اعتبار کیا جائے اور عُر وہ کے معنے ایسی چیز کےبھی ہیں جس کی طرف انسان ضرورت کے وقت رجوع کرے.اور عُر وہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو ہمیشہ قا ئم رہے اور کبھی ضا ئع نہ ہو.اور عُر وہ بہترین مال کو بھی کہتے ہیں (۱) اگر عُر وہ کے معنے دستہ کے لئے جا ئیں تو اس آ یت کا یہ مطلب ہو گا کہ دین کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی لطیف چیز قرار دیا ہے جو کسی بر تن میں پڑی ہوئی ہو اور محفوظ ہو اور انسا ن نے اس بر تن کا دستہ پکڑ کر اسے اپنے قبضہ میں کر لیا ہو(۲) پھر عُر وہ کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے جس کا انسا ن سہارا لے لیتا ہے تا کہ اسے گر نے کا ڈر نہ رہے.جیسے سیڑ ھیوں پر چڑھنے کے لئے انسان کو رسّہ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے.اسی طرح دین بھی اس رسّہ کی طر ح ایک سہارا ہے.اسے مضبوط پکڑ لینے سے گر نے کا ڈر نہیں رہتا.(۳) عروہ کہہ کر یہ بھی بتا یا کہ اگر انسان اسے مضبوطی سے پکڑ لے تو وہ ہر مصیبت کے وقت اس کے کام آتا ہے.(۴) عُروہ میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ صرف دین ہی انسا ن کے کام آ نے والی چیز ہے.اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی.با قی تمام تعلقات عارضی ہو تے ہیں اور مصیبت کے آ نے پر ایک ایک کر کے کٹ جاتے ہیں.بیشک انسان اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اپنا بہترین رفیق قرار دیتا ہے.لیکن بسا اوقات ان سے کمزوری یا بے وفائی ظا ہر ہو جاتی ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ حقیقی تعلقات وہی ہیںجن کی بنیادیں دین اور مذہب پر استوار کی جائیں اور انہی میں بر کت ہوتی ہے.اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا١ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں.وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر النُّوْرِ١ؕ۬ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ۠ الطَّاغُوْتُ١ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ روشنی کی طرف لاتا ہے.اور جو کافر ہیں ان کے دوست نیکی سے روکنے والے (لوگ )ہیں.اور انہیں روشنی سے مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ١ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ١ۚ نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں.وہ لوگ آگ (میں پڑنے) والے ہیں.
Page 452
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَؒ۰۰۲۵۸ وہ اس میں پڑے رہیںگے.تفسیر.فر ما تا ہے.اللہ مو منوں کا دوست اور مددگار ہے.اور وہ ایمان لانے والوں کو اندھیروں سے روشنی کی طر ف لاتا ہے.عر بی زبان کے محا ورہ میں کا میابی کی طرف لے جا نے کو ظلمت سے نور کی طرف لے جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے.خواہ وہ کامیابی جسما نی ہو یا روحانی.پس اس سے مراد مو منوں کی جماعت کو ہر قسم کی روحا نی اور جسما نی کامیابیوں کی طرف لے جا نا اور انہیں ہر قسم کی نا کا میوں اور تکا لیف سے نجا ت دلا نا ہے.وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ۠ الطَّاغُوْتُ١ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ۠ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ.یہاں طا غوت سے مراد وہ لوگ ہیں جو شیطا ن کے قا ئم مقام ہو تے ہیں.وہ لوگوں کو اس تھوڑی بہت ہدایت سے بھی جس پر وہ قا ئم ہو تے ہیں دور پھینک دیتے ہیں.یہ مت خیال کر و کہ کفار میں نور کہاں سے آ یا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نہیںکیا تھا.اس وقت ابو جہل ایسا بُرا نہیں تھا جیسا کہ اس وقت تھا جب کہ وہ مارا گیا.بات یہ ہے کہ صداقت کے انکار سے انسان کے قلب پر زنگ لگ جاتا ہے اور ہو تے ہو تے وہ تھوڑا بہت نور جو اس کے دل میں ہو تاہے وہ بھی جا تا رہتا ہے.حضرت مسیح مو عودعلیہ الصلوۃ السلام کی بعثت سے پہلے بعض صداقتیں ایسی تھیں جن کو لوگ مانتے تھے مگر اب ان کا بھی انکار کر رہے ہیں.مثلاً مسلمان خطیب حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کی بعثت سے پہلے اپنے منبر وں پر کھڑے ہو ہو کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ع مو سیٰ کجا عیسٰی کجا اس بات کا ہے سب کو غم مگر اب ان کی کتا بوں سے یہ شعر غا ئب ہو گیا ہے.اسی طرح ان میںرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعتقاد رکھنے والے لو گ بھی مو جود تھے جیسا کہ مولوی محمد قا سم صا حب نا نو توی ہیں.انہوں نے اپنی کتا ب تحذیرالناس میں صاف لکھا ہے کہ بغیرشر یعت کے نبی ہو سکتا ہےمگر اب سب لو گ اس کا انکار کر رہے ہیں.پس نبی کے آ نے سے پہلے بعض لو گو ں کے عقا ئد اچھے ہو تے ہیں مگر جب وہ نبی کا انکار کر دیتے ہیں اور انہیں ان کے پہلے عقیدہ کی رُو سے پکڑا جا تا ہے تو وہ اپنا پہلو بچا نے کے لئے اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں.لیکن جو شخص صداقت کو قبول کر تا ہے وہ روز بروز اپنے ایمان میں بڑھتا چلا جاتا ہے.
Page 453
میں اوپر بتا چکا ہوں کہ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ میں خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرما یا ہے کہ جو لو گ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں ان کواللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ترقی کی طر ف لے جاتا ہے مگر چو نکہ دنیا میں انسان کو قدم قدم پر مشکلات پیش آتی رہتی ہیں جن کو دیکھ کر بعض لوگو ں کو یہ دھو کا لگ جاتا ہے کہ اگراللہ تعالیٰ نے مو منوں کی کا میا بی کا وعدہ کیا ہے تو پھر انہیں مشکلات کیوں پیش آ تی ہیں.اس لئے یاد رکھنا چا ہیے کہ یہ وعدے قومی طور پر کئے گئے ہیں نہ کہ انفرادی طور پر.پس انفرادی تکا لیف اور مشکلات کو اس وعدہ کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے.اگر کو ئی شخص مارا جاتاہے لیکن اس کے مر نے سے قوم کو فا ئدہ پہنچتا ہے تو وہ مر تا نہیں بلکہ زندہ ہو تا ہے.ورنہ ظاہری تکا لیف کو دیکھا جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہید کر دئیے گئے تھے مگر وہ نا کام نہیں ہو ئے بلکہ اپنے مقصد میںکا میاب ہو ئے اور جس اصول کی خاطر انہوں نے قربانی پیش کی تھی وہ اصول آ ج بھی قا ئم ہے اور قیامت تک قائم رہےگا.اسی طرح بعض انبیاء بھی شہید ہوئے.مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف لکھا ہے کہ وہ مارے گئے تھے(حمامۃ البشریٰ.روحانی خزائن جلد ۷ صفحہ ۲۱۵).پس جب نبی بھی مارا جا سکتا ہے تو اور کون ہے جو اس قسم کی تکالیف سے محفوظ رہے.پس کسی فرد کا مارا جانا قوم کی نا کامی کی دلیل نہیں ہوتی.جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بیشک مارے گئے مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یز ید کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا اور امام حسینؓ کی سب عزت کر تے ہیں اور ان کا نام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کی بڑی تعظیم کی جاتی ہے.اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ١ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.اوپر بتا یا تھا کہ اسلام کے لئے جبر کر نے کی ضرورت نہیں کیو نکہ ہدایت گمراہی کے مقابلہ میں ممتا ز ہو چکی ہے.اور جنگ کا حکم تمہیں اس لئے دیا گیا ہے کہ دشمن تم پر حملہ کر رہا ہے.اب اس آ یت میں بتا یا کہ تمہارا انجام اچھا ہو گا اور تمہارے مخا لفوں کا بُرا.خدا تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو ایسی تبا ہیوں سے دو چار کرےگا جن سے وہ ہمیشہ غیظ و غضب کی آگ میں جلتے رہیں گے اور اپنے چاروں طرف دوزخ ہی دوزخ پا ئیں گےجس سے نکلنے کا انہیں کو ئی راستہ نظر نہیں آئےگا.اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ کیا تجھے اس شخص کی خبر نہیں پہنچی جو اس (غرور کی) وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکومت دی رکھی تھی ابراہیم ؑ سے اس کے الْمُلْكَ١ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ١ۙ قَالَ رب کے متعلق بحث کرنے لگ گیا.(یہ اس وقت ہوا) جس وقت ابراہیم نے (اسے) کہا کہ میرا ربّ وہ ہے جو
Page 454
اَنَا اُحْيٖ وَ اُمِيْتُ١ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ زندہ کرتا اور مارتا ہے.(اس پر )اس نے کہا (کہ) میں( بھی) زندہ کرتا اور مارتا ہوں.ابراہیم نے کہا (کہ اگر یہ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ بات ہے) تو اللہ( تعالیٰ تو) سورج کو مشرق (کی طرف) سے لاتا ہے.(اب) تو اسے مغرب( کی طرف) سے لے آ.كَفَرَ١ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَۚ۰۰۲۵۹ اس پر وہ( کافر) مبہوت ہو( کر رہ) گیا.اور( یہ ہونا ہی تھا کیونکہ) اللہ ظالم لوگوں کو (کامیابی کی )راہ نہیں دکھاتا.حل لغات.حَآجَّ حَآجَّہٗ کے معنے ہیں خَا صَمَہٗ (اقرب) اس سے جھگڑا کر نے لگ گیا.حَآ جَّ کا لفظ قرآن کریم میں جتنی جگہ استعمال ہوا ہے بُرے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے سوائے ایک جگہ کے کہ وہاں اس کے ایک اور معنے لئے جا سکتے ہیں.لغت والے بھی یہی لکھتے ہیں کہ یہ لفظ اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا.پس اس کے معنے ہیں کج بحثی.مجا دلہ.مکابرہ.مُلْکُ کے معنے بادشاہت کے بھی ہیں اور ملک کے بھی ہیں.(اقرب) اِحْیَا ءُ کے معنے ہیں زندہ کر نا.خو شی پہنچا نا.نمو کی طا قت دینا.آ باد کر نا.(اقرب) اِمَا تَۃٌ کے معنے ہیں مُردہ کر نا.رنج پہنچا نا.نمو کی طا قت نکال ڈالنا.(اقرب) بُھِتَ کے معنے ہیں چہرہ کا رنگ اُڑ گیا.گھبرا گیا.مُنہ بند ہو گیا اور کو ئی جواب نہ بن سکا.(اقرب) تفسیر.اس آ یت کے متعلق مفسّرین کا خیال ہے کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام اور ایک کافر با دشاہ میں جس کا نام نمرود بیان کیا جا تا ہے ہستی باری تعالیٰ پر بحث ہو ئی تھی.جب حضرت ابراہیمؑ نے اسے کہا کہ میرا ربّ وہ ہے جو زندہ کر تا اور مارتا ہے.تو اس نے کہا کہ ایسا تو میں بھی کر لیتا ہوں.چنا نچہ اس نے چند قیدی منگوا ئے جن میں سے بعض کو اُس نے چھوڑ دیا اور بعض کو قتل کر دیا.یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم ؑ نے سمجھا کہ میری پہلی دلیل تو کار گر نہیں ہوئی اب میںکوئی اور دلیل پیش کروں.چنا نچہ انہوں نے کہا کہ میرا ربّ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اگر تُو بھی ربّ ہے تو اسے مغرب سے لے آ.اس پر وہ خا موش ہو گیا اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام غا لب آ گئے(درمنثور زیر آیت ھذا).مگرمیرے نزدیک ان کی یہ قیاس آ رائی درست نہیں.کیو نکہ اس طرح تو دونوں ہی خا موش ہو گئے تھے.
Page 455
پہلے سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خا موش ہو گئے اور دوسرے سوال پر وہ خا موش ہو گیا.پس میرے نزدیک یہ تو جیہہ صحیح نہیں کیو نکہ اگر یہی مراد ہوتی اور وہ ایسا ہی جھو ٹا اور کذّاب تھا اور اپنے آپ کو خدا بنا رہا تھا تو وہ یہ جواب بھی دے سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے تومَیںہی لا رہا ہوں.تم اپنے خدا کو کہو کہ وہ اسے مغرب سے لے آئے مگر اس نے یہ نہیں کہا.بلکہ قر آن کریم بتا تا ہے کہ وہ خا موش ہو گیا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا.بلکہ بات دراصل کچھ اور تھی.ورنہ بحث میں تو کو ئی چپ ہوا ہی نہیں کرتا.لوگ بیہودہ باتوں پر بھی بحث کر تے چلے جاتے ہیں.حتّٰی کہ اس امر پر بھی بحث کر تے ہیں کہ انسان کا وجود ہے یا نہیں.اور لوگ پھر بھی خاموش نہیں ہوتے.لیکن وہ خا موش ہو گیا.اس سے صا ف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کو ئی ایسی بات تھی جس کے متعلق اس نے سمجھا کہ اگر میں نے اس کا جواب دیا تو میں مصیبت میں پھنس جاؤںگا.اس لئے سوائے خامو شی کے اس کے لئے اور کو ئی چارہ نہ رہا.جیوش انسا ئیکلو پیڈیا میں اس بحث کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ جب ’’ حضرت ابراہیم ؑ اس با دشاہ کے سامنے جس کا نام نمرود تھا پیش ہوئے تو اس نے کہا کیا تُو نہیں جانتا کہ میں خدا ہوں اور دنیا کا حا کم ہوں اور میں ہی مارتا اور زندہ کر تا ہوں چو نکہ ان کا سب سے بڑا خدا سورج دیوتا سمجھا جاتا تھا اور اسے آ قا بھی کہا جاتا تھا.حضرت ابراہیمؑ نے اسے کہا کہ اگر تُو خدا اور دنیا کا حا کم ہے تو کیوں سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق کی طرف نہیں چڑھا تا.اگر تو خدا اور دنیا کا حاکم ہے تو مجھے بتا کہ میرے دل میں اس وقت کیا ہے اور یہ کہ میرا آئندہ کیاحال ہو گا.اس پر نمرود کی زبان بند ہو گئی اور وہ حیران رہ گیا.حضرت ابراہیمؑ نے اپنی بات کو جاری رکھا.اور کہا کہ تُو کو نس کا بیٹا ہے اور اسی طرح کا ایک فانی وجود.تو اپنے باپ کو موت سے نہیں بچا سکا اورنہ خود اس سے بچ سکتا ہے.‘‘ (جیوش انسا ئیکلو پیڈیا زیر لفظ Abraham) اسی طرح طا لمو د میں بھی حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کی اس بحث کا ذکر کیا گیا ہے.لیکن طا لمود اور قر آ ن کریم کے بیان میں فرق ہے.قرآ ن کریم میں زندہ کر نے اور مارنے کا ذکر پہلے ہے اور سورج کی تبدیلی کا ذکر پیچھے.لیکن طا لمود میں سورج کی تبدیلی کا ذکر پہلے ہے اور احیا ء و اماتت کا بعد میں.دوسرے طالمود میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمردو بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے آپ کو کہاکہ تُو بتوں کی پو جا کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا.جن کو آ گ جلا دیتی ہے ان کی کیا پو جا کروں.اس نے کہا.پھر آگ کی کیوں نہیں کرتا.انہوں نے کہا.جسے
Page 456
پا نی بجھا دیتا ہے.اس کی کیا پو جا کروں؟ اس نے کہا.پھر پا نی کی کیوں نہیںکرتا.انہوں نے کہا.پا نی کو تو بادل لاتا ہے.اس نے کہا.پھر بادلوں کی کیوں نہیں کرتا.انہوں نے کہا.ان کو ہوا اُڑا لے جاتی ہے.اس نے کہا.پھر ہوا ہی کی کر.انہوں نے کہا.انسان اس سے بھی بچا ؤ کر لیتا ہے اور بچ جاتا ہے اور وہ اس پر غالب نہیں آ تی.اس نے کہا.پھر مجھے پُو جو.کیونکہ میں انسا نوں کا خدا ہوں.انہوں نے کہا کہ تمہارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں.یہ بحث جس کا طا لمود میں ذکر کیا گیا ہے خود اپنی ذات میں اس امرکا ثبوت ہے کہ سورج کا ذکر پہلے نہیں ہوا بلکہ پہلے احیاء اورا ما تت کا ہی ذکر ہوا ہے ورنہ سورج کے ذکر کے بعد تو بحث آ گے چل ہی نہیں سکتی تھی کیو نکہ سورج ان میں سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا اور اس کو ہر قسم کی کا میا بیوں اور نا کا میوں اور تر قی اورتنزل کا اصل باعث قرار دیا جاتا تھا.چنا نچہ نیلسنز انسا ئیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ میرےؔ ڈاک ان کا بڑا خدا تھاجسے سورج کی شعاع یا دن کی روشنی سمجھا جاتا تھا.اور اسے بنی نوع انسان کی تر قی اور تنزل کا اصل با عث قرار دیا جاتا تھا.(دیکھو نیلسنز انسا ئیکلو پیڈیا زیر لفظ ببلو نیا) پھر عقلاً بھی قر آن کریم کا کلام ہی درست ثا بت ہوتا ہے.اوّل اس لئے کہ بحث میں نیچے سے اوپر تر قی ہوتی ہے.پس موت اور حیات کا ذکر لا زماً سورج سے پہلے ہونا چاہیے نہ کہ بعد میں.دوسرے درمیان میں نمرود کے چپ ہو جانےکا ذکر بتا تا ہے کہ یہ وا قعہ سب سے آ خر میں ہوا.تیسرے نمرود کے سا منے پیش تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے کے جرم میں ہوئے تھے.اس کا یہ سوال کہ میں خدا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں بحث کے دوران میں پیدا ہوا ہے.ورنہ بے جوڑ کلام ہو جاتا ہے.قرآن کریم یہی بتا تاہے کہ بحث فِیْ رَبِّہٖ تھی.یعنی خدا ئے واحد کے بارہ میںبحث میں با دشاہ نے کہیں کہہ دیا کہ دیکھ میں تجھے تباہ کر دوں گا کیو نکہ میں حاکم ہوں.آپ نے فر ما یا تباہی یا آبادی تو خدا کے اختیار میں ہے.اس پر اس نے اس احیاء اور اماتت کو اپنی طرف منسوب کیا.اور کہا کہ نہیں میرے اختیار میں ہے.آپ نے جھٹ اس کو پہلی بحث کے مطا بق پکڑا کہ پھر سورج عبث ہوا.اور وہ چُپ ہو گیا.اس واقعہ کے نا موں وغیرہ میں گو فر ق ہے لیکن یہو دی تا ریخ میں اس وا قعہ کو جس طرز پر بیان کیا گیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی وا قعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم اشارہ کرتا ہے اور جس پر اَلَمْ تَرَ کے الفا ظ بھی دلالت کر تے ہیںکیو نکہ اَلَمْ تَرَ کے ساتھ کسی بے نشان واقعہ کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا مگر یہودی بیان حسب معمول آ گے پیچھے ہو گیا ہے.طالمود میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیمعلیہ السلام کی نمرود سے یہ بحث کنعان میں آنے سے پہلے ہو ئی تھی.
Page 457
میرے نزدیک حضرت ابراہیمعلیہ السلام نے نمرود سے جو یہ کہا کہ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ میرا ربّ وہ ہے جو زندہ کر تا اور مارتا ہے.تو اس سے ان کی مراد ظا ہری موت اور حیات نہیں تھی.بلکہ کا میابی اور نا کامی اور عزّت اور ذلّت اور آ بادی اور بر بادی مراد تھی.چو نکہ آ پ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو چکا تھا کہ وہ آپ کو کنعان کا ملک دےگا اور آپ کی اولاد کو غیر معمولی ترقی حا صل ہو گی.اس لئےآپ نے فرمایا کہ میرا ربّ وہ ہے جواحیاء اور اماتت کی صفت اپنے اندر رکھتا ہے.وہ جس کو چاہتا ہے عزّت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے.جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناکام کر دیتا ہے.اور جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شکست دے دیتا ہے.اِس پر اُس نے کہا اَنَا اُحْیٖ وَ اُمِیْتُ.یہ بات تو میرے اختیار میں بھی ہے کہ میں جسے چاہوں ترقی دے دوں اور جسے چاہوں ذلیل کر دوں.جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے سورج ان کا سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا.اور بادشاہ بھی اُس کی پرستش کرتا تھااس لئے حضرت ابراہیمعلیہ السلام نے اُسے جواب میں کہا کہ خدا تعالیٰ نے تو یہ سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے اور اس طرح دنیا کو نفع پہنچاتا ہے.لیکن اگر دنیا کو نفع پہنچانا تیرے اختیار میں ہے تو یہ جو سورج چڑھا ہوا ہے اِس کو مغرب سے مشرق کی طرف لوٹا دے.وہ دن کا وقت تھا اور سورج چڑھا ہوا تھا.حضرت ابراہیمعلیہ السلام نے کہا اسے واپس لوٹا دے یعنی اسے پیچھے کو لے جا یا یہ کہا کہ اسے مغرب سے چڑھا لا.گویا انہوں نے اسے کہا کہ اس پر اپنی حکومت قائم کرکے دکھا.حضرت ابراہیمعلیہ السلام کا مدّعا یہ تھا کہ اگر دنیا کا نفع و نقصان تمہارے ہا تھ میں ہے تو پھر سورج کیا کر تا ہے اور اگر سورج نفع و نقصان پہنچا تا ہے تو نفع و نقصان پہنچا نے اور مالک ہو نے کا تمہارا دعویٰ با طل ہے.اس پر جیسا کہ تا ریخ بتا تی ہے.وہ مبہوت ہو کر لا جواب ہو گیا کیونکہ اگر وہ جواب دیتاتو یا تووہ یہ کہتا کہ میں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ سورج ہی پہنچا تاہے اور تر قی اور تنزل اسی کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں.اور اگر وہ ایسا کہتا تو اس سے اس کایہ دعویٰ با طل ہو جاتا کہ اَنَا اُحْيٖ وَ اُمِيْتُ.اور اگر وہ یہ کہتا کہ میں ہی یہ تمام کام کر تا ہوں سورج نہیں کرتا اور نفع نقصان بھی میرے ہی اختیار میں ہے سورج کے اختیار میں نہیں تو اس پر اس کی قوم دشمن ہو جاتی کیو نکہ وہ سورج کی پر ستش کر تی تھی بلکہ وہ خود بھی سورج کا پر ستار تھا.اس وجہ سے وہ کو ئی جواب نہ دے سکا اور خا موش ہو گیا.اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ کا ثبوت دیا ہے اور بتا یا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی مشکلات میں کس طرح ان کی مدد کر تے اور انہیں ظلمات سے نور کی طرف اور نا کا میوں سے
Page 458
کامیا بیوں کی طرف لے جاتے ہیں.اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا١ۚ اور (کیا تو نے )اس شخص کی مثل( کوئی آدمی دیکھا ہے )جو ایک ایسے شہر کے پاس سے گزرا جس کی یہ حالت تھی کہ وہ قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا١ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ اپنی چھتوں کے بل گِرا ہوا تھا.(اس کو دیکھ کر )اس نے کہا کہ اللہ (تعالیٰ) اس کی ویرانی کے بعد اسے کب آباد مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ١ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ١ؕ قَالَ لَبِثْتُ کرے گا؟ اس پر اللہ( تعالیٰ) نے اسے سو سال تک (خواب میں) مارے رکھا.پھر اسے اٹھایا (اور) فرمایا( اے يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ١ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ میرے بندے )تو کتنے عرصہ تک (اس حالت میں )رہا ہے.اس نے کہا میں (اس حالت میں )ایک دن یا دن کا فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ١ۚ وَ انْظُرْ اِلٰى کچھ حصہ رہا ہوں.تب (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا( یہ بھی ٹھیک ہے )اور تو (اس حالت میں )سو سال تک بھی رہا ہے.حِمَارِكَ وَ لِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ اب تو اپنے کھانے اور پینے (کے سامان) کی طرف دیکھ کہ وہ سڑا نہیں.اور اپنے گدھے کی طرف (بھی )دیکھ(اور كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا١ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ١ۙ ان دونوں کا سلامت رہنا دیکھ کر سمجھ لے کہ تیرا خیال بھی اپنی جگہ درست ہے اور ہمارا خیال بھی) اور ایسا ہم نے اس
Page 459
قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۰۰۲۶۰ لئے کیا تا تجھے لوگوں کے لئے ایک نشان بنائیں.اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم انہیں کس طرح اپنی اپنی جگہ رکھ کر جوڑتے ہیں.پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں.پس جب اس پر( حقیقت) پورے طور پر ظاہر ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ (تعالیٰ )ہر ایک چیز پر قادر ہے.حلّ لُغات.اَوْکَا لَّذِیْ کَاف مثال کےلئے بھی آ تا ہے اور تا کید کے لئے بھی.اسی طرح تشبیہ اور تمثیل کے لئے بھی آتا ہے.یہاں پہلے معنوں کے لئے ہے.(اقرب) خَا ویَۃٌ خَوٰ ی یَخْوِیْ خِوَاءً سے نکلا ہے.کہتے ہیں خَوَی الْبَیْتُ: سَقَطَ وَ تَھَدَّمَ.گھر گِر گیا.فَرَغَ وَخَلَا.گھر خا لی ہو گیا اور ویران ہو گیا.(المنجد) بَلْ حرف ہے جو اضرؔاب کے معنے دیتا ہے.یعنی بات کو پھیر کر دوسری طرف لے جانا.یہ اضراب دو طرح کا ہو تا ہے ایک تو انکار کی غرض سے جیسے قرآن کر یم میں آ تا ہے وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ١ؕ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ.(الانبیاء: ۲۷) یعنی مشرک کہتے ہیں کہ رحمٰن خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے.لیکن یہ بات غلط ہے جن کو یہ لو گ خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں.اضراب کی دوسری قسم میں ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف مضمو ن کو پھیر نا مقصود ہو تا ہے.بَلْ سے پہلے جملہ کی تردید مدّ نظر نہیں ہو تی.اس آیت میں بھی بَلْ سے پہلے کی بات بھی درست ہے اور بعد کی بھی صرف ایک نئے مضمون کی طرف متو جہ کیا گیا ہے.(المنجد) نُنْشِزُھَا نَشَزَ کے معنے ہیں اِرْتَفَعَ اُٹھا.اور اَنْشَزَہٗ کے معنے ہیں رَفَعَہٗ اسے اٹھا یا یا کھڑا کیا.پس نُنْشِزُ ھَا کے معنے ہیں ہم ان کو کھڑا کر تے ہیں.یا ہم انہیں اُٹھا تے ہیں.(اقرب) تفسیر.مفسّر ین کہتے ہیں کہ یہ عزیر نبی کا وا قعہ ہے.وہ ایک دفعہ ایک تبا ہ شدہ بستی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کی تبا ہی اور خستہ حا لی کو دیکھ کر کہا کہ خدا تعالیٰ اس بستی میں رہنے والوں کو ان کی موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ اس پرخدا تعالیٰ نے انہیں مار ڈالا اور وہ سو سال تک اسی حالت میں مُردہ پڑے رہے.اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لو گوں کو آ باد کر دیا اور انہیں زندہ کر کے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ کیسا قادر ہے اور وہ مردوں کو کس طرح زندہ کیا کر تا ہے.جب وہ سو سال کے بعد زندہ ہو کر اُٹھ بیٹھے تو خدا تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنے کھا نے کو دیکھ کہ وہ بھی ابھی تک سڑا نہیں اورپھر اس نے ان کے گدھے کو بھی زندہ کر دیا اور اس کی گلی سڑی ہڈیوں پر
Page 460
ہڈیوں پر گو شت پو ست چڑھا دیا.میرے نز دیک اگر یہ وا قعہ اسی طرح ہوا ہو جس طرح مفسّرین بیان کر تے ہیں تو خود اس آیت کے مختلف ٹکڑے اس بیان کو با طل قراد دیتے ہیں چنا نچہ پہلی بات جو ان معنوں کو رد کر تی ہے وہ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا کے الفاظ ہیں.یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اس نبی کا سوال صرف بستی کے متعلق تھا کہ اللّہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرےگا؟ یہ سوال نہیں تھا کہ مُردے کس طرح زندہ ہوںگے؟ اگر مُردوں کے زندہ ہونےکا سوال ہوتا تو کیا ان کے سامنے روزانہ کئی لوگ مرتے نہیں تھے؟ اور جب وہ روزانہ یہ نظارہ دیکھتے تھے کہ لوگ مر کر زندہ نہیں ہوتے تو اس دن ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھ کر ان کے دل میں مردوں کے زندہ ہونے کے متعلق کیسے سوال پیدا ہو گیا؟ اور اگر ان کا سوال صرف بستی کے دوبارہ زندہ کئے جانے کے متعلق تھا تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بستی کے مردہ ہونے سے اس کا اجڑنا اور زندہ ہونے سے اس کا آباد ہونا ہی مراد ہواکرتا ہے.مردوں کے زندہ ہونے سے اس سوال کا کوئی تعلق نہیں.دوسرا سوال یہ ہے کہ اَنّٰى سے مراد ’’کب تک‘‘ ہے یا ’’کیسے ‘‘ ہے.اگر کسی سوال کرنے والے کے جواب میں ’’سو سال ‘‘کا لفظ بولا جائے تو اس کے یہی معنے ہوںگے کہ سائل کا سوال ’’کب تک ‘‘کا ہے’’کیسے‘‘ کا نہیں.ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سائل تو یہ سوال کرے کہ یہ بستی کس طرح زندہ ہو گی اور جواب یہ دیا جائے کہ سو سال کے بعد زندہ ہو جائے گی.سو سال کے الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ سوال کب کے متعلق ہے نہ کہ کیفیت کے متعلق.اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ.اللہ تعالیٰ نے اسے سو سال تک مارے رکھا پھر زندہ کر دیا.اب سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ اگر تو حضرت عزیر کی یہ غرض تھی کہ وہ دیکھیں کہ مُردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں تو اُن کو مار کر پھر زندہ کر دینے سے یہ غرض پوری نہیں ہو سکتی تھی.کیونکہ موت کے بعد وہ یہ کس طرح جان سکتے تھےکہ مُردہ کس طرح زندہ ہو ا کرتا ہے.اور اگر ان کی دوبارہ حیات سے اللہ تعالیٰ کا منشاء پورا ہو گیا تھا تو پھر وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا پر یہ اعتراض پڑتا ہےکہ اللہ تعالیٰ نے صرف گدھے کو ہی مار کر اور پھر اسے زندہ کر کے انہیں اپنی قدرت کا نظارہ کیوں نہ دکھا دیا؟ خود انہیں سو سال تک کیوں مارے رکھا؟ آخر اپنی موت سے تو اس بات کا پتہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ مُردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے.یہ تو دوسرے کو دیکھ کر ہی پتہ لگتاہے.اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے گدھے کو بھی مارنا تھا تو پھر ان کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں نہ کیا گیا کہ اس بستی میں سے ہی کسی ایک کو مار کر اسے زندہ کر کے دکھا دیا جاتا خود
Page 461
عزیر کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟اسی طرح سوال یہ ہے کہ انہوں نے کونسی بات پوچھی تھی جس کا جواب یہ دیا گیا کہ َاُنْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ.ان کاسوال تو یہ تھا کہ بستی کس طرح زندہ ہو گی؟ مگر جواب یہ دیا گیا کہ تُو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ کہ وہ سڑا نہیں.پس اوّل تو ھٰذِہٖ کا لفظ بتلاتا ہے کہ اس جگہ لوگوں کے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونےکا کوئی سوال نہیں بلکہ صرف شہر کی آبادی اور اس کی دوبارہ حیات کا سوال تھا.دوسرے مِائَۃَ عَامٍ میں بتلا دیا کہ اَنّٰی کے ساتھ’’کب‘‘ کا سوال کیا گیا تھا نہ کہ ’’کیسے ‘‘ کا.یعنی سوال کیفیت کے متعلق نہ تھا بلکہ زمانہ کے متعلق تھا.غرض مفسّرین کے بیان کردہ واقعہ پر کئی اعتراضات پڑتے ہیں.پہلا اعتراض تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیر کو کیوں مارا.اگر وہ نبی تھا تو یہ اس کے سوال کا اچھا جواب دیا کہ اسے سو سال تک مارے رکھا.اس عرصہ میں اس کے بیوی بچے بھی مر گئے اور اسے ایک صدی کے بعد غیر لوگوںمیں زندہ کر کے بٹھلا دیا.اس شخص کو مار کر زندہ کرنے کی غرض زیادہ سے زیادہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مُردوں کو زندہ کیا کرتا ہے.مگر سوال یہ ہے کہ پھر گدھے کو گوشت پوست چڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟اس ثبوت کے لئے تو صرف گدھے کا مر کر جینا ہی کافی تھا.خود عزیر کو مارنے کی کوئی ضرورت نہ تھی.پھر یہ سنت اللہ کے بھی خلاف ہے کہ کسی مُردہ کو زندہ کیا جائے.اور پھر اگر خدا تعالیٰ نے انہیں سو سال تک مارے رکھا تو اس کے ثبوت میں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو!تمہارا کھانا سڑا نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ کھانا پینا تو الگ رہا دنیا ہی بدل چکی ہے جواس بات کا ثبوت ہے کہ تُو سو سال تک واقعہ میں مرا رہا تھا.مگر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا.غرض ان تمام امور پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مفسّرین نے اس واقعہ کو جس رنگ میں پیش کیا ہے وہ درست نہیں.اب میں اس واقعہ کی وہ حقیقت بیان کرتا ہوں جو میرے نزدیک درست ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اس شخص کی طرف دیکھ جو ایک بستی یا گائوں پر سے ایسی حالت میں کہ وہ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا گذرا اور اس نے سوال کیا کہ الہٰی یہ بستی اپنی ویرانی کے بعد کب آباد ہو گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے سو سال تک مارے رکھا (یعنی خواب میں ) اور پھر اسے اٹھایا.اور اس سے پوچھا کہ تُو کتنی دیر تک رہا ہے.اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ.اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تو درست ہے لیکن اس کے علاوہ ہم تجھے ایک اور بات بھی بتاتے ہیں کہ تو سو سال تک بھی رہا ہے.تیری بات کے سچا ہونےکا تو ثبوت یہ ہے کہ تو اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ وہ سڑا نہیں.لیکن میری بات کے
Page 462
سچا ہونےکا ثبوت یہ ہےکہ ہم نے تجھے کشفی حالت میں سو سال کا نظارہ دکھایا ہے اور جب یہ رؤیا پورا ہو گا اس وقت لوگوں کو تسلیم کرنا پڑےگا کہ تیرا خدا کے ساتھ سچا تعلق تھا.جب اس پر یہ حقیقت روشن ہو گئی.تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوںکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اوراس کے آگے یہ کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ایسی اُجڑی ہوئی بستی کو اپنے فضل سے پھر دوبارہ آباد کر دے.حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ اس بستی سے یروشلم مراد لیا کرتے تھے.جسے بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ وہ آدمی جویروشلم کے پاس سے گزرا حزقیل نبی تھا.جس پر خدا تعالیٰ نے اس بات کاانکشاف کیا کہ ایک سو سال تک یہ شہر دوبارہ آباد ہو جائےگا(حقائق الفرقان جلد ۱ زیر آیت ھذا).اور میرے نزدیک یہی بات درست ہے.یہاںاس بستی کے متعلق خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں.جس کے معنے یہ ہیںکہ وہ گائوں اپنی چھتوںپر گرا ہوا تھا.یعنی پہلے چھتیںگریں اور پھر ان پر دیواریں گر گئیں.کیونکہ جو مکان عدم استعمال کی وجہ سے گریںبالعموم پہلے ان کی چھتیںگرتی ہیں.کیونکہ چھتوں میں لکڑی ہوتی ہے اور لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے جب چھتیںگر جاتی ہیں تو پھر بارش کی وجہ سے ننگی دیواریں بھی گرنے لگتی ہیں اور اس صورت میں وہ دیواریں چھتوں پر آ گرتی ہیں.اسی حالت کو واضح کرنے کے لئے خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں.ورنہ جو مکان زلزلہ وغیرہ کی قسم کے حادثات سے گرتے ہیں.ان کی دیواریں پہلے گرتی ہیں اور چھت ان پر آگرتی ہے.ان الفاظ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ اس گائوں کی ویرانی کا سبب زلزلہ وغیرہ نہ تھا.بلکہ اس کے باشندوں کا شہر چھوڑ کر چلا جانا اس کا موجب تھا.بہر حال حزقیل نبی کے دل میںیروشلم کی بربادی دیکھ کر یہ سوال پیداہوا کہ خدا تعالیٰ اس بستی کو کب زندہ کرے گا؟ بستی کو زندہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ مردہ لوگ کس طرح زندہ ہوںگے.بلکہ اس کا مطلوب وہی ہے جو دوسر ی جگہ بستیوں کو زندہ کرنے کے متعلق قرآن کریم نے بیان کیا ہے فرما تا ہے.وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا.لِّنُحْيِۧ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّ نُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَاۤ اَنْعَامًا وَّ اَنَاسِيَّ كَثِيْرًا.(الفرقان: ۴۹،۵۰)یعنی ہم نے بادل سے پاک و صاف پانی اتارا ہے.تاکہ اس کے ذریعہ ہم مُردہ ملک کو زندہ کریں اور اسی طرح اس پانی سے اپنے پیدا کیے ہوئے چارپائیوں اور بہت سے انسانوں کو سیراب کریں.اسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے.وَ اَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا(ق: ۱۲) ہم بارش کے ذریعہ مُردہ شہر کو زندہ کیا کرتے ہیں.پس مُردہ شہر کو زندہ کرنے کے معنے ویران شہر کو آباد اور خوشحال کرنے کے ہوتے ہیں.حضرت حزقیل نے بھی یہی سوال کیا کہ الٰہی ! یہ شہر کب آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں رئویا میں بتایا کہ سو سال کے عرصہ میں آباد ہو جائے گا.
Page 463
یہ رئویا جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے حزقیل نبی کی کتاب میں بھی پائی جاتی ہے صرف اتنا فرق ہے کہ حزقیل نبی کی کتاب میں سو سال کی میعادکا ذکر نہیں.یہ قرآن کریم کی صداقت اور اس کے کامل ہونےکا ایک زبردست ثبوت ہے کہ جو ضروری امور پچھلی کتب میں بیان نہیں ہوئے قرآن کریم نے ان کو بھی بیان کر دیا ہے اور اس طرح ان کی کمی کو پورا کر دیا ہے.بہر حال حزقیل باب ۳۷ میں لکھا ہے.’’خدا وند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے خداوند کی روح میں اٹھا لیا اوراس وادی میں جو ہڈیوں سے بھر پور تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چو گرد پھرایا.اور دیکھ وے وادی کے میدان میں بہت تھیں اور دیکھ وے نہایت سوکھی تھیں.اور اس نے مجھے کہا کہ اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں جی سکتی ہیں.میں نے جواب میں کہا کہ اے خداوند یہوواہ تو ہی جانتا ہے.پھر اس نے مجھ سے کہا کہ تو ان ہڈیوں کے اوپر نبوت کر اور ان سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیو! تم خدا وند کا کلام سنو.خداوند یہوواہ ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تمہارے اندر میں روح داخل کروں گا.اور تم جیؤگے.اور تم پر نسیں بٹھا لاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تمہیں چمڑے سے مڑھوں گا اور تم میں روح ڈالوں گا اور تم جیؤ گے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں.سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی.اور جب میں نبوت کرتا تھاتو ایک شور ہوا.اور دیکھ ایک جنبش اورہڈیاں آپس میں مل گئیں.ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے اور جو میں نے نگاہ کی تو دیکھ نسیں اور گوشت ان پرچڑھ آئے اور چمڑے کی ان پر پوشش ہو گئی.پر ان میں روح نہ تھی.تب اس نے مجھے کہا کہ نبوت کر.تُوہوا سے نبوت کر.اے آدم زاد! اور ہوا سے کہہ کہ خداوند یہوواہ یوںکہتا ہے کہ اے سانس! تو چاروں ہوائوں میںسے آ.اور ان مقتولوںپر پھونک کہ وے جیئیں.سو میں نے حکم کے بموجب نبوت کی اور ان میں روح آئی اور وے جی اٹھے اور اپنے پائوںپر کھڑے ہوئے.ایک نہایت بڑا لشکر.تب اس نے مجھ سے کہا کہ اے آدم زادیہ ہڈیاں سارے اسرائیل ہیں.دیکھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی.ہم تو بالکل فنا ہو گئے.اس لئے تو نبوت کر اور ان سے کہہ کہ خداوند یہوواہ یو ں کہتا ہے کہ دیکھ اے میرے لوگو میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا.اور تمہیں تمہاری قبروں سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کی سر زمین میں لاؤں گا اور میرے لوگوجب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو تمہاری قبروں سے نکالوں گا تب جانوگے کہ خدا وند میں ہوں اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گااور تم جیئو گے.اور میں تم کو تمہاری
Page 464
سر زمین میں بسائوں گا.تب تم جانو گے کہ مجھے خداوند نے کہااور پورا کیا." (حزقیل باب۳۷ آیت ۱ تا ۱۴) یہ پیشگوئی ہے جو حزقیل نبی نے کی.اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اس وقت بابل میں قید تھے.وہ اس بستی کے پاس سے کب گزرے؟ سو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گزرنا بھی خواب میں ہی ہو.جیسا کہ بائیبل کے الفاظ سے ظاہر ہے.دوسرا جواب یہ ہے کہ نبو کد نضر جو بابل کا بادشاہ تھا اس نے ۵۸۶ قبل مسیح یروشلم پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا.اور اس کا ایک حصہ گرا دیا تھا.وہ وہاں کے بادشاہ اور اس کے خاندان کے تمام افراد کو پکڑ کر اپنے ملک میں لے گیا.اسی طرح شہر کے تمام شرفاء اور بڑے بڑے کا ریگروں کو بھی قید کر کے لے گیا.اور سوائے چند رذیل لوگوں کے وہاں کوئی باقی نہ رہا(جیوش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ یروشلم Jerusalam).حضرت حزقیل بھی ان قیدیوں میں ہی تھے(حزقیل باب ۳ آیت ۱۵) جنہیں نبو کد نضر نے گرفتار کیا.ان کے متعلق بحث ہوئی ہے کہ انہیں اس نے کیوں پکڑا؟ اور مؤرخین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ نبوکد نضر کا مقابلہ کرو اور اپنے ملک کو نہ چھوڑو اس لئے وہ ان کو بھی قیدکر کے لے گیا.پرانی تاریخوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ جن شہروں کو گراتے اورویران کرتے تھے وہاں کے قیدیوں کو وہ ان کے اوپر سے گزارتے تھے تاکہ انہیں اپنی ذلّت اور بیچارگی کا احساس ہو.میرے نزدیک جب وہ پکڑے گئے اور یروشلم کے اوپر سے گزارے گئے اس وقت انہوں نے اس کے متعلق خدا تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے ؟ شہر گرا دیا گیا ہے.سب بڑے بڑے لوگ قید کر کے لے جائے جا رہے ہیں.ایسی خطرناک تباہی کے بعد اب یہ شہر دوبارہ کب آباد ہو گا؟ وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا کے الفاظ بھی اسی امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یروشلم کے تباہ ہوتے ہی ان کے دل میںیہ خیال پیدا ہواجب کہ گری ہوئی چھتیں انہیں نظر آ رہی تھیں.ورنہ بعد میں تو لوگ سا مان اٹھا کر لے جاتے ہیں.اس وقت ان کے دل میںیہ خیال گزرا کہ الٰہی !یہ شہر دوبارہ کب آباد ہو گا.ہم تو سب قید ہو کر جا رہے ہیں.اس پر اللہ تعا لیٰ نے ان کو سو سال کی موت کا نظارہ دکھا یا.یعنی کشفی رنگ میں انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور سو سال کے بعد پھر زندہ ہوئے ہیں.اور خوا بوں میں ایسا ہونا کو ئی تعجب انگیز امر نہیں.انسان خواب میں مر تا بھی ہے اور مختلف قسم کے نظارے بھی دیکھتا ہے.حضرت حز قیل چو نکہ اپنی قوم کے نبی تھے.اس لئے ان پر کشفی رنگ میں مو ت کی کیفیت وارد کر نے سے مرا د
Page 465
درحقیقت بنی اسرائیل کی موت تھی اور اللہ تعا لیٰ اس ذریعہ سے انہیں یہ بتا نا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل سو سال تک غلامی اور ادبار کی حالت میں رہیں گے اس کے بعد ان کو ایک نئی زندگی عطا کی جا ئےگی اور وہ اپنے شہر میں وا پس آ جائیںگے.اس میں کو ئی شبہ نہیں کہ اس جگہ رؤیا کا کو ئی لفظ نہیں.مگر قر آ ن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ بعض دفعہ رؤیا کا تو ذکر کر تا ہے مگر رؤیا کا لفظ استعمال نہیں کرتا.چنا نچہ حضرت یو سفعلیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بتا یا کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاند اور سورج وغیرہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو انہوں نے رؤیا کا لفظ استعمال نہیں کیا.پس یہ ضروری نہیں ہو تا کہ خواب کے ذکرمیں خواب کا لفظ بھی استعمال کیا جائے.جب وہ یہ نظارہ دیکھ چکے تو ان کو اٹھایا گیا.یعنی ان کی کشفی حالت جاتی رہی.اور خدا تعالیٰ نے ان سے پو چھا کہ كَمْ لَبِثْتَ بتا تو کتنے عرصہ تک اس حالت میں رہا انہوں نے عر ض کیا لَبِثْتُ یَوْمًا اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ.میں تو صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں.محا ورہ میں اس کے یہ معنے ہیں کہ اچھی طرح معلوم نہیں.چنا نچہ یہ محاورہ قرآن کریم میں بعض دوسرے مقا مات پر بھی استعمال کیا گیا ہے.فر ما تا ہے.کَمْ لَبِثْتُمْ فِی الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِیْنَ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَآدِّيْنَ ( المو منون: ۱۱۳،۱۱۴) یعنی اللہ تعالیٰ کفار سے فر ما ئے گا کہ تم زمین میںکتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں.تُوگننے والوں سے پو چھ لے یعنی ہم بہت تھوڑا عر صہ رہے ہیں یا ہمیں معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ رہے.حضرت حزقیل کا یہ جواب ادب کے طور پر تھا کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کا اس سوال سے کیا منشاہے.یعنی بات تو ظاہر ہے کچھ دیر ہی سو یا ہوں.قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ.اللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ اس بات کے علاوہ جو تیرے دل میں ہے ہم ایک اور بات بھی بتاتے ہیں.اور وہ یہ کہ تُو سو سال تک رہا ہے.یہاں بَلْ میں پہلے قول کی نفی نہیں کی گئی بلکہ ایک اور بات بیان کی گئی ہے.جیسے قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فر ما یا ہے.قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى.وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى.بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا.وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى.(الاعلٰی:۱۵ تا ۱۸) یعنی جو شخص پاک بنے گا وہ یقیناً کامیاب ہو گا بشر طیکہ اس نے اپنے ربّ کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا.مگراے مخا لفو! تم ورلی زندگی کو آ خرت پر تر جیح دیتے ہو.حا لا نکہ آ خرت کہیں زیادہ بہتر اور دیر پا ہے.اس آ یت میں بَلْ سے پہلے کی بات بھی درست ہے اور بعد کی بھی.اسی طرح اس آیت میں بَلْ کے لفظ سے حضرت حز قیل کے اس خیال کی کہ وہ دن یا دن کا کچھ حصہ اس حالت میں رہے تر دید مدّ نظر نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایک اور مضمون کی طرف ان کے ذہن کا انتقال کیا ہے اور بتا یا ہے کہ ایک نقطہ نگاہ سے دیکھوتو تم نے سو سال اس حالت میں گزارے ہیں.مگر چونکہ نبی کا قول بھی اپنی جگہ درست تھا اس لئے اس خیال سے کہ نبی خدا تعالیٰ کے قول کو مقدم رکھ کر اپنے
Page 466
خیال کو غلط نہ قرار دےدے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ ہم تمہارے خیال کو رد نہیں کرتے وہ بھی درست ہے.چنانچہ دیکھو تمہاراکھانااچھی حالت میں ہے سڑا نہیں اور تمہارا گد ھا بھی تندرست اپنی جگہ پر کھڑا ہے جس سے ثابت ہوا کہ تمہارا خیال بھی کہ تم صرف چند گھنٹے اس حالت میں رہے ہو اپنی جگہ درست ہے.ورنہ جو سو سال تک واقعہ میں مرا رہا ہو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ اپنا کھانا دیکھ وہ سڑانہیں.اور پھر فرمایا کہ یہ رؤیا ہم نے اس لیے دکھائی ہے تاکہ ہم تجھے لوگوں کےلئے ایک نشان بنائیں.اب تو ان مُردہ ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم ان کو کس طرح کھڑا کرتے ہیں اور ان پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں.اس کشف اور الہام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی کہ ایک سو سال تک یہ شہرآباد ہو جائےگا.چنانچہ ٹھیک سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی ترقی اور آبادی کی صورت پیدا کر دی.یروشلم کی تباہی دو دفعہ ہوئی ہے ایک دفعہ ۵۹۷ قبل مسیح میں اور دوسری دفعہ یروشلم کی بغاوت پر ۵۸۶ قبل مسیح میں.اس جگہ سو سال دوسری تباہی سے ہی لئے جائیں گے کیونکہ شہر کو اسی میں برباد کیا گیا تھا.اس کے بعد ۵۱۹ قبل مسیح میں یر و شلم کی دوبارہ بنیاد رکھی گئی اور تیس سال تک تعمیر جاری رہی جس کے نتیجہ میں ۴۸۹ قبل مسیح میں یر وشلم صحیح طور پر آ باد ہوا.پس درمیانی فاصلہ قر یباً سو سال(۹۸سال) کا ہی ثا بت ہوتا ہے.( جیوش انسائیکلو پیڈیا ،بلیکس بائیبل ڈکشنری زیر لفظ Jerusalam) وَ انْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا کے الفاظ یہود کے اس قول کے مطا بق استعمال کئے گئے ہیں جس کا حز قیل نبی کی کتا ب میں بھی ذکر آ تا ہے کہ ’’ ہماری ہڈیاں سو کھ گئیں اورہماری امید جا تی رہی.ہم تو بالکل فنا ہو گئے‘‘ (حز قیل باب ۳۷ آ یت ۱۱) اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا یا کہ تم ایک بار پھر زندہ ہو گے اور پھر اپنی کھو ئی ہوئی طا قت اور عظمت حا صل کرو گے.غرض اس واقعہ کے متعلق با ئیبل سے رؤیا بھی مل گیا.بنی اسرا ئیل کی ہڈیوں پر گو شت کا چڑھا یا جا نا بھی ثابت ہو گیا.اسی طرح حزقیل نبی کو پکڑ کر لے جا نا بھی ثابت ہو گیااور پھر سو سال کےبعدیروشلم کا دوبارہ آباد ہو نا بھی تاریخ سے ثابت ہو گیا.حز قیل نبی کوپہلے تو صدمہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا یا کہ یہ ہمیشہ کی تبا ہی نہیں تو انہوں نے کہا اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.خدا یا !اب میری تسلّی ہو گئی ہے.اور گو بظاہر ان حالات کا بد لنا نا ممکن نظر آ تا ہے مگر یہ بات یقیناً ہو کر رہے گی.اور خدا تعالیٰ دوبارہ اس شہر اور قوم کو تر قی عطا فرمائے گا.
Page 467
وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى ١ؕ قَالَ اَوَ اور (اس واقعہ کو بھی یاد کرو) جب ابراہیم ؑ نے کہا کہ اے میرے ربّ مجھے بتا کہ تو مُردے کس طرح زندہ کرتاہے.لَمْ تُؤْمِنْ١ؕ قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ لِّيَطْمَىِٕنَّ قَلْبِيْ١ؕ قَالَ فَخُذْ فرمایا کہ کیا تُو ایمان نہیں لا چکا.(ابراہیم ؑ نے )کہا کیوں نہیں (ایمان تو بے شک حاصل ہو چکا ہے) لیکن اپنے اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ اطمینان قلب کی خاطر( میںنے یہ سوال کیا ہے).فرمایا.اچھا تُو چار پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ سدھا جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا١ؕ وَ اعْلَمْ لے.پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک (ایک )حصہ رکھ دے.پھر انہیں بلا وہ تیری طرف تیزی کے ساتھ چلے اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌؒ۰۰۲۶۱ آئیں گے.اور جان لے کہ اللہ غالب (اور) حکمت والا ہے.حل لغات.صُرْ ھُنَّ صُرْکے ساتھ جب اِلٰی کا صلہ آ جا ئے تو اس کے معنے اپنی طرف مائل کر لینے کے ہو تے ہیں.کا ٹنے کے نہیں ہو تے.ہاں جب یہ لفظ اِلیٰ کے صلہ سے خالی ہو تو اس وقت اس کے معنے کاٹنے کے ہی ہوتے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں.صَارَالشَّیْءَ قَطَعَہٗ.اسے کاٹ دیا.پس صُرْھُنَّ اِلَیْکَ کے معنے ہیں.ان کو اپنے ساتھ سِدھالے.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے تم اس واقعہ کو بھی یاد کرو جب ابراہیمؑ نے کہا تھا.کہ اے میرے ربّ ! مجھے بتا کہ تُو مُردے کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا.کیا تو ایمان نہیں لا چکا؟ حضرت ابراہیمعلیہ السلام نے اَوَلَمْ تُؤْمِنْ کے جواب میں بَلٰی کہا.جس سے اس عقیدہ کا اظہار مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ مُردے زندہ کر سکتا ہے.اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے گویا انہوں نے اس کے متعلق کسی شک کا اظہار نہیں کیا بلکہ اقرار کیا کہ خدا تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے اور مجھے اس پر کامل ایمان حاصل ہے.
Page 468
بَلٰی کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے خواہ نفی ہو یا اثبات اس سے مراد ’’ہاں‘‘ ہی ہوتی ہے.اگر اس جگہ نَعَمْ کا لفظ ہوتا تو اس کے یہ معنے بھی ہو سکتے تھے کہ ہاں مجھے ایمان نہیں ہے.مگر اس جگہ بَلٰی کا لفظ رکھا گیا ہے.جس سے یہ شبہ دُور ہو گیا کیونکہ اس کے معنے ہر صورت میں اثبات ہی کے ہوتے ہیں.ایمان کے بعد لٰکِن کا لفظ رکھا گیا ہے.جو استدراک کےلئے آتا ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے ایمان تو ہے کہ خدا تعالیٰ مردے زندہ کر سکتا ہے لیکن میں اس سے ایک زائد بات چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ میرے دل کو بھی اطمینان حاصل ہو جائے کہ تو میری قوم کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا.جیسے ایک شخص جو بیمار ہو اسے ایمان تو ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ بیماروں کو اچھا کر سکتا ہے.لیکن اطمینان نہیں ہو سکتا کہ اسے بھی اچھا کرےگا.یہ اطمینان خدا کے بتانے سے ہی ہو سکتا ہے.یا مثلاً ہر شخص جانتا ہے کہ بھوک کے بعد لوگ سیر ہو جایا کر تے ہیں مگر کیا اس سے ایک فاقہ زدہ کو یہ یقین ہو جائےگا کہ مجھے بھی کھانا مل جائےگا اور میں سیر ہو جائوں گا ؟ پس ایمان تو امر غیب کے متعلق ہوتا ہے جو انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے.اور کسی چیز کے ہونے یا ہو سکنے کے متعلق اس کے یقین کامل کو ظاہر کرتا ہے.لیکن اطمینان کا لفظ دو چیزوں کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے.ایک شک کے مقابلہ میں.دوسرے کرب و اضطراب کے مقابلہ میں.وہ اطمینان جو شک کے مقابلہ میں ہوتا ہے.وہ یہاں مراد نہیں.بلکہ وہی اطمینان مراد ہے.جو کرب اور اضطراب کے مقابلہ میں ہوتا ہے.کیونکہ اس سے پہلے اثباتِ ایمان موجود ہے.حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا کہ خدا تعالیٰ احیاء موتیٰ کر سکتا ہے مگر وہ اپنی قوم کے متعلق بھی یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اس پر الٰہی فضل نازل ہو گا اور وہ بھی زندہ قوم بن جائےگی.اللہ تعالیٰ نے فرمایا.تُو چار پرندے لے اور ان کو اپنے ساتھ سدھا لے.پھر ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دے.پھر انہیں بُلا.وہ تیری طرف تیزی کے ساتھ چلے آئیں گے.اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اورحکمت والا ہے.لوگ اس آیت کے یہ معنے کرتے ہیں کہ چار پرندے پکڑ کر ان کا قیمہ کر لے.اور ان کو اپنی طرف لے لے.لیکن یہ بالکل غلط اور محاورہ کے خلاف معنے ہیں.کیا کوئی شخص قیمہ کر کے اسے اپنی طرف بھی لیا کرتا ہے.پس یہ کوئی معنے نہیں کہ قیمہ کر کے اسے اپنی طرف لے لے.اس کے یہی معنے ہیں کہ توان کو اپنے ساتھ سدھالے.(مفردات واقرب الموارد) جُزْءً ا کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ بتلاتا ہے کہ یہاںقیمہ کرنا ہی مراد ہے مگر یہ بھی غلط ہے.جُزْءٌ
Page 469
کے معنے ایک پرندے کے ٹکڑے کے نہیں بلکہ چاروں پرندوں کا جزء مراد ہے جو ایک کا عدد ہے.اس کی مثال قرآن کریم کی اس آیت سے ملتی ہے کہ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ.لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ١ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ.(الحجر:۴۴.۴۵) یعنی جہنم سب کفار کے لئے مقررہ جگہ ہے.اس کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ کے لئے کفار کا ایک حصہ مقرر ہو گا.اس جگہ جُزْءٌ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے.لیکن کوئی شخص یہ معنی نہیں کرتا کہ کفار کا قیمہ کر کے اس قیمہ کا تھوڑا تھوڑا حصہ سب دروازوں میں ڈال دیا جائےگا.بلکہ سب مفسرین متفق ہیںکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ کافر ایک دروازہ سے لے جائے جائیں گےا ور کچھ دوسرے سے اور کچھ تیسرے سے اور کچھ چوتھے سے(روح البیان زیر آیت الحجر ۴۴،۴۵).پس سورہ حجر کی اس آیت نے بتلا دیا کہ جب جزء کالفظ ایک جماعت پر بولا جائے تو اس سے اس جماعت کے افراد مرادہوتے ہیں.اور انہی معنوں میں جزء کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے اور مراد ہر پرندہ کا جزء نہیں بلکہ چار کاجزء ہے.اور معنے یہ ہیں کہ ہر چوٹی پر ایک ایک پرندہ رکھ دے.یہ واقعہ جس کا اوپر ذکر کیا گیاہے.اگر ظاہری ہوتاتو اس پر بہت سے اعتراض پڑتے ہیں.اوّل یہ کہ احیاءِ موتی کے ساتھ پرندوںکے سدھانے کا کیاتعلق؟دوم.چار پرندے لینے کے کیا معنے؟ کیا ایک سے یہ غرض پوری نہ ہوتی تھی؟ سوم ؔپہاڑوں پر رکھنے کا کیا فائدہ کیاکسی اور جگہ رکھنے سے کام نہ چلتا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری کلام نہیں بلکہ مجازی کلام ہے.حضرت ابراہیمعلیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الٰہی احیاء موتی کا جو کام تو نے میرے سپرد کیا ہے اسے پورا کر کے دکھا.اور مجھے بتا کہ میری قوم میںزندگی کی روح کس طرح پیدا ہو گی جبکہ میں بڈھا ہوں.اور کام بہت اہم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو یہ کام ہو کر رہےگا.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہوکر تو ضرور رہےگا مگر میں اپنے اطمینان کے لئے پوچھتا ہوں کہ یہ مخالف حالات کس طرح بدلیں گے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو چار پرندے لےکر سدھا.اور ہر ایک کو پہاڑ پر رکھ دے.پھر ان کو بلا.اور دیکھ کہ وہ کس طرح تیری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.یعنی اپنی اولاد میں سے چار کی تربیت کر وہ تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے.اس احیاء کے کام کی تکمیل کریںگے.یہ چار روحانی پرندے حضرت اسماعیلؔ.حضرت اسحاقؔ حضرت یعقوبؔ اور حضرت یوسف علیھم السلام ہیں.ان میں سے دو کی حضرت ابراہیمعلیہ السلام نے براہ راست تربیت کی اور دو کی بالواسطہ.پہاڑ پر رکھنے کے معنے بھی یہی تھے کہ ان کی نہایت اعلیٰ تربیت کر کیونکہ وہ بہت بڑے درجہ کے ہوںگے.گویا پہاڑ پر رکھنے میں ان کے رفیع الدرجات ہونے کی طرف
Page 470
اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بلندیوں کی چوٹیوںتک جا پہنچیں گے.اسی طرح چار پرندوں کو علیحدہ علیحدہ چار پہاڑوںپر رکھنے کے یہ معنے تھے کہ یہ احیاء چار علیحدہ علیحدہ وقتوں میں ہو گا.غرض اس طرح احیاء قومی کا وہ نقشہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھاانہیں بتا دیا گیا.اسی طرح بعد کے زمانہ کے لئے بھی اس میں حضرت ابراہیمعلیہ السلام کی قوم کی چار ترقیوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ مُردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں؟اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم کو میری طاقتوں پر ایمان نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ایمان تو ہے وَ لٰكِنْ لِّيَطْمَىِٕنَّ قَلْبِيْ.یہ زبان کا ایمان ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آ پ مر دوں کو زندہ کر تے ہیں اور اقرار کر نا پڑتا ہے کہ کرتے ہیں مگر دل کہتا ہے کہ یہ طا قت میری اولاد کی نسبت بھی استعمال ہو.میں چا ہتا ہوں کہ یہ نشان اپنے نفس میں بھی دیکھوں اس پراللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ تمہاری قوم چار دفعہ مردہ ہو گی اور ہم اسے چار دفعہ زندہ کریں گے.چنا نچہ ایک دفعہ حضرت موسٰےعلیہ السلام کے زما نہ میں.ان کے ذریعہ حضرت ابراہیمعلیہ السلام کی آواز بلند ہوئی.اور یہ مردہ زندہ ہوا.پھر حضرت عیسٰی علیہ السلام کے ذریعہ حضرت ابراہیمؑ کی آ واز بلند ہوئی.اوریہ مردہ زندہ ہوا.پھر آ نحضرت صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے ذریعہ وہی آ واز بلند ہوئی اور اس مردہ قوم کو زندگی ملی.اور چو تھی بار حضرت مسیح مو عود علیہ الصلوۃ السلام کے ذریعہ ابراہیمی آ واز پھیلی اور وہی مردہ زندہ ہوا.چا ر دفعہ ابراہیمی نسل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ وازیں دیں اور چا روں دفعہ وہ دوڑ کر جمع ہو گئی.پہلا پر ندہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا یا اور اطمینان قلب حا صل کیا وہ مو سوی اُمّت تھی.دوسرا پر ندہ عیسوی اُمت تھی.تیسرا پر ندہ آ نحضرتصلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے جلا لی ظہور کی حا مل اور مظہر محمدی جما عت تھی.اور چو تھا پر ندہ آ پ ؐ کے جما لی ظہور کی مظہر جماعتِ احمدیہ ہے.جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو راحت پہنچائی اور آ پ نے کہا کہ واقعی میرا خدا زندہ کرنے والا ہے بَلٰى وَ لٰكِنْ لِّيَطْمَىِٕنَّ قَلْبِيْ کا بھی یہی مطلب تھا کہ حضور زبان تو اقرار کرتی ہے.اور میں ہر روز دیکھتا ہوں کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں.اس کا مجھے کس طرح انکار ہو سکتا ہے.لیکن اگر میری اولاد ہدایت نہ پائے تو مجھے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا.پس اطمینان قلب کےلئے میں نشان مانگتا ہوں.میری عقل وفکر میرے ہوش وحواس اور میرا مشاہدہ کہتا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں.مگر دل کہتا ہے کہ میں خود کیا تعریف کروں جب تک یہ پتہ نہ لگے کہ میری اولاد میں بھی یہ نشان ظاہر ہو گا.خدا تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ تمہاری اولاد کو چار دفعہ زندہ کیا جائے گا.اور چار بار اُس پر خاص فضل
Page 471
نازل ہو گا.چنانچہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت.دوسری دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت.تیسری دفعہ رسول کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے وقت اور چوتھی دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر خدا تعالیٰ نے اپنا خاص فضل نازل کیا اور انہیں روحانی لحاظ سے زندہ کر دیا غرض اس میں قریب اور بعید دونوں زمانوں کیلئے پیشگوئی کی گئی تھی.جو اپنے اپنے وقت میں بڑی شان سے پوری ہوئی.اور خدا تعالیٰ کا عزیز اور حکیم ہونا ظاہر ہوگیا.مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ( تعالیٰ )کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے اس فعل) کی حالت اس دانہ کی حالت کے حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ مشابہ ہے جو سات بالیں اگائے (اور )ہر بالی میں سو دانہ ہو اور اللہ جس کے حَبَّةٍ١ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ١ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۰۰۲۶۲ لئے چاہتا ہے (اس سے بھی) بڑھا (بڑھا کر )دیتا ہے.اور اللہ وسعت دینے والا (اور)بہت جاننے والا ہے.حلّ لُغات.یُضَاعِفُ کُلّیاتِ ابی البقاء میں لکھا ہے کہ اَقَلُّ الضِّعْفِ مَحْصُوْرٌ وَّ ھُوَ مِثْلُ الْوَاحِدِ وَ اَکْثَرُ ہٗ غَیْرُ مَحْصُوْرٍ یعنی ضعْف کی اقلّ ترین تعداد دوگنا ہوتی ہے.لیکن زیادہ جتنی بھی ہو سب ضعف میں شمار ہوتی ہے.تفسیر.سابقہ رکوع میں اِحیاءِ قومی کی تین مثالیں دی گئی ہیں.اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ ایک چوتھی تمثیل بیان فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر تم دینی کاموں کے لئے اپنے اموال خرچ کرو گے تو جس طرح ایک دانہ سے اللہ تعالیٰ سات سودانے پیدا کر دیتا ہے.اسی طرح وہ تمہارے اموال کو بھی بڑھائے گا.بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے گا.جس کی طرف وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ میں اشارہ ہے.چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا.حضرت ابوبکر ؓ نے بیشک بڑی قربانیاں کی تھیں.مگر خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کا پہلا خلیفہ بنا کر انہیں جس عظیم الشان انعام سے نوازا اس کے مقابلہ میں ان کی قربانیاں بھلا کیا حیثیت رکھتی تھیں! اسی طرح حضرت عمرؓ نے بہت کچھ دیا مگر انہوں نے کتنا بڑا
Page 472
انعام پایا.حضرت عثمانؓ نے بھی جو کچھ خرچ کیا اس سے لاکھوں گنا زیادہ انہوں نے اسی دنیا میں پالیا.اسی طرح ہم فرداً فرداً صحابہؓ کا حال دیکھتے ہیں تو وہاں بھی خدا تعالیٰ کا یہی سلوک نظر آتا ہے.حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ کو ہی دیکھ لو.جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس تین کروڑ روپیہ جمع تھا(اسد الغابۃ عبد الرحمن بن عوف ).اس کے علاوہ اپنی زندگی میں وہ لاکھوں روپیہ خیرات کرتے رہے.ا سی طرح صحابہؓ نے اپنے وطن کو چھوڑا تو ان کو بہتر وطن ملے.بہن بھائی چھوڑے تو ان کو بہتر بہن بھائی ملے.اپنے ماں باپ کوچھوڑا.تو ماں باپ سے بہتر محبت کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم مل گئے.غرض اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والا کبھی بھی جزائے نیک سے محروم نہیں رہا.وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ کہہ کر بتایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام دینے میں بخل تو تب ہو جبکہ خدا تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہو.مگر وہ تو بڑی وسعت والا اور بڑی فراخی والا ہے اور پھر وہ علیم بھی ہے.جانتا ہے کہ وہ شخص کس قدر انعام کا مستحق ہے.اگر کوئی شخص کروڑوں گنا انعام کا بھی مستحق ہو.تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دینے کی قدرت رکھتا ہے دنیا میں ہم روزانہ یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ زمیندار زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سات سودانے بنا کر واپس دیتا ہے.پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا کیسے ممکن ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جائے.اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کئے ہوئے مال کا کم از کم سات سو گنا بدلہ ضرور ملتا ہے.اس سے زیادہ کی کوئی حدبندی نہیں.اگر انتہائی حد مقرر کر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو محدود ماننا پڑتا.جو خدا تعالیٰ میں ایک نقص ہوتا اسی لئے فرمایا کہ تم خدا کی راہ میں ایک دانہ خرچ کروگے تو کم از کم سات سوگنا بدلہ ملے گا.اور زیادہ کی کوئی انتہا نہیں اور نہ اس کے انواع کی کوئی انتہا ہے.حضرت مسیح علیہ السلام نے تو انجیل میں صرف اتنا فرمایا تھا کہ’’ اپنے لئے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں.‘‘ (متی باب ۶ آیت ۲۰) لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے خزانہ میں اپنا مال جمع کروگے تو یہی نہیں کہ اسے کوئی چرائے گا نہیں بلکہ تمہیں کم از کم ایک کے بدلہ میں سات سو انعام ملیں گے اور اس سے زیادہ کی کوئی حدبندی نہیں.پھر حضرت مسیح ؑ کہتے ہیں.وہاں غلہ کو کوئی کیڑا نہیں کھا سکتا.مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ صرف کیڑے سے ہی محفوظ نہیں رہتا بلکہ ایک سے سات سو گنا ہو کر واپس ملتا ہے.بیشک اللہ تعالیٰ کسی انسان کی مدد کا محتاج نہیں مگر وہ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اگر کسی کام کے کرنے کا انہیں موقع دیتا ہے تو اس لئے کہ وہ ان کے مدارج کو بلند کرنا چاہتا ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اسے نئے سرے سے ایک جماعت قائم کرنی پڑتی ہے.مگر اس کی ابتداء ایسی ہوتی ہے کہ دنیا اسے دیکھ کر یہ خیال بھی نہیں کر سکتی کہ وہ کامیاب ہو جائے گا لیکن خدا تعالیٰ اس
Page 473
کے ذریعے دنیا کے نظام کو بدل دیتا ہے.اس وقت دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک زندہ خدا موجود ہے جس کے آگے کوئی بات ان ہونی نہیں.ایسے انبیاء کے زمانہ میں ان کی قوموں اور امتوں کو موقعہ دیا جاتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں.چونکہ وہ وقت ایک نئی دنیا کی تعمیر کا ہوتا ہے اس لئے لوگوں کو قربانیوں کا موقعہ دیا جاتا ہے.اور وہی وقت ثواب کے حصول کا ہوتا ہے.اوپر کے بیان کردہ مفہوم کے علاوہ اس آیت میںغلّہ کی زیادتی کے امکانات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے.اور بتایا گیا ہے کہ بعض حالات میں یہ ممکن ہے کہ ایک دانہ سات بالیں نکالے او رہربال میں ایک ایک سودانہ ہو.یعنی ایک دانہ سات سو گنا ہو جائے.یا ایک من بیج سے سات سومن گندم پیدا ہو.او رپھر اسی پر بس نہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھادے.اس اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہمارے ملک میں عام طور پر فی ایکڑ تیس سیر بیج ڈالا جاتا ہے.اگر ایک دانہ سے سات سو دانہ تک کی پیداوار ہو تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ ایک ایکڑ سے ۲۱۰۰۰ سیر اناج پیدا ہو سکتا ہے.اور یہ ۵۲۵ من بنتے ہیں.گویا قرآنی اصول کے مطابق ۵۲۵ من فی ایکڑ پیدا وار ہو سکتی ہے.بلکہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھی بڑھا سکتا ہے.اس وقت لوگ اوسطاً پانچ من فی ایکڑ پیداوار پر گذارہ کر رہے ہیں.اگر یہ پیداوار بڑھ کر سوا پانچ سو من فی ایکڑ ہو جائے اور زیادتی کا جو وعدہ ہے وہ نہ بھی پورا ہو تب بھی دنیا میں اتنی گندم ہو سکتی ہے.جو موجودہ آبادی سے کئی گنا زیادہ آبادی کے لئے بھی کافی ہو.پھر ابھی کئی غیرآباد علاقے پڑے ہیں انہیں آباد کیا جائے تو پیداوار میں اور بھی زیادتی ممکن ہے.مثلاً افریقہ کے بعض علاقے ہیں جو ابھی غیرآباد ہیں.آسٹریلیا او رکینیڈا کے علاقوں میں بھی ابھی بہت کم آبادی ہے.اسی طرح روس کے بعض حصوں میں بھی زمینیں خالی پڑی ہیں.اگر ان علاقوں کی طرف توجہ کی جائے اور صحیح طور پر زراعت کی جائے اور سائینس کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے تو دنیا میں پیداوار کے لحاظ سے ایک عظیم الشان تغیر پیدا ہو سکتا ہے اور آبادی میں بھی کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے.اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.پھر خرچ کرنے کے بعد مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًى ١ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ١ۚ نہ کسی رنگ میں احسان جتاتے ہیں اورنہ کسی قسم کی تکلیف دیتے ہیں ان کے ربّ کے پاس ان (کے اعمال )کا بدلہ
Page 474
وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۰۰۲۶۳ (محفوظ )ہے.اور نہ تو انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.حلّ لُغات.اَلْمَنُّ کے معنے ہیں مَنَّ عَلٰی مَا صَنَعَ کسی پر احسان کر کے اُسے جتلانا.مثلاً کہتے ہیں.اَعْطَیْتُکَ کَذَا وَ فَعَلْتُ مَعَکَ کَذَا.میں نے فلاں وقت تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور تجھے یہ کچھ دیا تھا.عربوں کا محاورہ ہے کہ اَلْمَنُّ اَخُو الْمَنِّ.کہ احسان جتلانا کاٹ ڈالنے کے برابر ہے.مَنَّ کے معنے کاٹنے کے بھی ہوتے ہیں.چنانچہ دوسرا مَنَّ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے.(لسان العرب) اَذًی تکلیفؔ پہنچانا.گندیؔ بات.گندؔ.حدیث میں آتا ہے.اَمِیْطُوْا عَنْہُ الْاَذٰی.یعنی جب بچہ سات دن کا ہو جائے.تو وہ نجاست وغیرہ جو وہ اندرسے اپنے ساتھ لاتا ہے او ربال اس سے دُور کر دو.(لسان العرب) تفسیر.لَا يُتْبِعُوْنَ مَاۤ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّ لَاۤ اَذًى میں بتایا کہ خدا تعالیٰ کے راستہ میں مال خرچ کرنے کے بعد تمہاری یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ تم میں تکبر کے خیالات پیدا ہو جائیں او رتم یہ کہنا شروع کردو کہ ہم نے تو یہ کچھ دیا تھا.یوں مال قربان کیا تھا.یوں خدمتِ دین کی تھی.کیونکہ ایسا کرنا تمہاری نیکی کو ضائع کر دے گا.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۂ حجرات میں اَعراب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے یَمُنُّوْنَ عَلَیْکَ اَنْ اَسْلَمُوْا.(الحجرات:۱۸)اے محمد رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا بھی تجھ پر احسان جتاتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دے کہ لَا تَمُنُّوْا عَلَیَّ اِسْلَامَکُمْ.تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتائو.بَلِ اللّٰہُ یَمُنُّ عَلَیْکُمْ اَنْ ھَدَاکُمْ لِلْاِیْمَانِ.اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راہ دکھایا اور ایک سچے مذہب کو قبول کرنےیکی توفیق بخشی.اسی طرح مالی قربانیوں کے بعد دوسروں پر احسان جتانا سخت نادانی ہے.کیونکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ اس نے خدا کے لئے کام نہیں کیا تھا بلکہ بندوں کو ممنونِ احسان کرنے کے لئے کیا تھااور یہ چیز اسے ثواب سے محروم کر دیتی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی ایک مقام پر اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا ہے.’’ یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دےکر یا کسی اور رنگ سے کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کچھ احسان کرتے ہو.بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لئے بلاتا ہے.… پس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو.اور یا یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا
Page 475
کسی قسم کی خدمت کرتے ہیں.میں باربار تمہیں کہتا ہوں کہ خداتمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقعہ دیتا ہے… اگر تم اس قدر خدمت بجالائو کہ اپنی غیرمنقولہ جائدادوں کو اس راہ میں بیچ دو پھر بھی ادب سے دُور ہو گا کہ تم خیال کرو کہ ہم نے کوئی خدمت کی ہے… یہ تمام خیالات ادب سے دُور ہیں اور جس قدر بے ادب جلدتر ہلاک ہو جاتا ہے ایسا جلد کوئی ہلاک نہیں ہوتا.‘‘ (تبلیغ رسالت جلد دہم صفحہ ۵۵.۵۶) پھر اَذًی کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہئے کہ انسان کسی سے کوئی نیک سلوک کر کے اُسے اپنا غلام سمجھ لے اور پھر اس سے مستقل طور پرفائدہ اٹھانا شروع کر دے.یا چندہ دینے کے بعد کہے کہ میں نے تو اتنا چندہ دیا تھا.اب مجھے بھی مدد دی جائے اور میری مشکلات کو دُور کیا جائے.لَاخَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَاھُمْ یَحْزَنُوْنَ میں یہ خوشخبری دی کہ ایسے لوگ جو خالصۃً لِوجہ اللہ قربانیاں کریں گے وہ اپنے اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی خاص حفاظت میں آجائیں گے اور انہیں اپنے ماضی کی طرف سے بھی سکون قلب عطا کیا جائے گا اور اُن کا مستقبل بھی نہایت شاندار ہو گا.قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَاۤ اچھی بات(کہنا) اور( قصور) معاف کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا رسانی اَذًى ١ؕ وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ۰۰۲۶۴ (شروع )ہو (جائے )اور اللہ بے نیاز (اور) بردبار ہے.حلّ لُغات.قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ کے معنے ہیں کوئی بھلائی کی بات.مثلاً سائل کو نرمی سے ٹلا دیا جائے یا یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں.اَمر بِالْمَعْرُوْفِ کوئی نیکی کی بات کہہ دینا.(اقرب) مَغْفِرَۃٌ پردہ ڈال دینا.کسی کا گناہ معاف کر دینا.کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے درگذر کرنا.(اقرب)
Page 476
تفسیر.اس نصیحت کے بعد کہ خواہ کوئی دین کے لئے چندہ دے یا ان لوگوں کے لئے مالی قربانی کرے جو دین کے لئے اپنی زندگی وقف کرتے اور ہجرت کر کے مرکز میں آجاتے ہیں یا غرباء کی اعانت کے لئے مال خرچ کرے.اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ انہیں طعنہ دے کہ تم ہمارے چندوں پر پلتے ہو.اور اس طرح ان کو اذیت پہنچانے کا موجب بنے یا یہ کہے کہ ہم نے تم سے فلاں وقت یہ سلوک کیا تھا.اور ان پر احسان جتانے لگ جائے.اب بتاتا ہے کہ اس سے تویہ بہتر ہے کہ انسان اپنے منہ سے کوئی کلمۂ خیر ہی کہہ دیا کرے.مثلاً کوئی سائل آیا تو اس سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کرے اور آپ کے لئے اپنے فضل کے دروازے کھولے.اس طرح نرمی اور محبت کے ساتھ سائل کو ٹلادے.اور اس کے ساتھ پوری غمخواری اور اظہار ہمدردی کرے.اور مَغْفِرَت کا لفظ استعمال کر کے اس طرف توجہ دلائی کہ تم سے اگر کوئی شخص مدد مانگتا ہے.یا اپنی کوئی حاجت تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ تم پردہ پوشی سے کام لو.یہ نہ ہو کہ جگہ جگہ اس کی مالی کمزوری اور احتیاج کا ذکر کرتے پھرو.اسی طرح اس آیت کے یہ بھی معنے ہیں کہ امربالمعروف یا عبادتِ لسانی یا دعا کر دینا اور لوگوں کے گناہ معاف کر دینا اس صدقہ سے زیادہ بہتر ہیں جس کے بعد ایذا رسانی کا سلسلہ شروع ہو جائے.یعنی ایسی نیکیاں بجالانا جو جسمانی یا عقلی ہیں تمہارے لئے زیادہ اچھا ہے بہ نسبت اس کے کہ تم ایصالِ خیر کی طرف قدم بڑھائو مگر کر نہ سکو.وَاللّٰہُ غَنِیٌّ حَلِیْمٌ میں اس طرف اشارہ کیا کہ اگر روپیہ دے کر تم مَنّ اور اَذًی کے بغیر نہیں رہ سکتے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے.اسے تمہارے روپے کی کوئی ضرورت نہیں.وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو کھڑا کردے گا جو تم سے بہتر خدمت دین کرنے والے ہوں گے.اور حَلِیْمٌ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ گو وہ تمہاری خدمتوں سے بے نیاز ہے مگر اس کے حلم نے تقاضا کیاکہ وہ تم پر رحم کرے اور تمہیں ہلاکت سے بچائے چنانچہ اس نے ان احکام کے ذریعے تمہاری جنت کو تمہارے قریب کر دیا ہے.اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم چاہو تو اس کی صفت غنا کے ماتحت آجائو اور چاہو تو اس کی صفتِ حلیم سے فائدہ اٹھائو.اور ہر قسم کی نیکیاں محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے کرو.کوئی دنیوی منفعت اپنے سامنے نہ رکھو.
Page 477
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اے ایمان دارو!تم اپنے صدقات کو احسان جتانے اور الْاَذٰى١ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ تکلیف دینے (کے فعل) سے اس شخص کی طرح ضائع نہ کر لو جو لوگوں کے دکھانے کے لئے مال خرچ کرتا ہے.اور بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ١ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اس کی حالت تواس پتھر کی حالت کے مشابہ ہے جس پر کچھ مٹی (پڑی فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا١ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ ہوئی) ہو اور اس پر تیز بارش ہو.اور وہ اسے (مٹی دھو کرپھر )صاف پتھر(کا پتھر) کر دے.یہ( ایسے لوگ ہیں کہ ) مِّمَّا كَسَبُوْا١ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ۰۰۲۶۵ جوکچھ کماتے ہیں اس کا کوئی حصہ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور اللہ اس قسم کے کافروں کو (کامیابی کی )راہ نہیں دکھاتا.حلّ لُغات.صَفْوَانٌ کے معنے ہیں اَلصَّخْرُ الْاَمْلَسُ.چکنا پتھر.(اقرب) صَلْدًا اقرب الموارد میں لکھا ہے کہ مَالَایُنْبِتُ شَیْئًا مِنَ الْحِجَارَۃِ وَ مِنَ الْاَرْضِیْنَ یُقَالُ حَـجْرٌ صَلْدٌ وَ اَرْضٌ صَلْدٌ.یعنی جس پتھر یا زمین میں سے کچھ نہ اُگے اسے حَجْرٌ صَلْدٌ یا اَرْضٌ صَلْدٌ کہتے ہیں.تفسیر.فرماتا ہے.اے مومنو! مَنّ اور اَذًی کے ذریعہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرو.صدقات کے ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نتائج کو ضائع نہ کرو.كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِسے معلوم ہوتا ہے کہ ریا کے لئے کوئی کام کرنا خواہ کتنا ہی اچھا ہو بہت بُرا ہوتا ہے.مَنّ اور اَذًی والا صدقہ تو احسان جتانے یا تکلیف پہنچانے کے نتیجہ میں باطل ہوتا ہے مگر ریا والے کا صدقہ تو ریا کا خیال آتے ہی باطل ہو جاتا ہے.بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَنّ وَ اَذًی والے کا صدقہ بھی ریاء الناس والے کی طرح ضائع چلا جائے گا کیونکہ گو اس شخص کے دیتے وقت ریا مدنظر نہ تھی مگر اس کے دل کے گوشوں
Page 478
میں ضرور مخفی تھی ورنہ وہ مَنّ وَ اَذًی سے کیوں کام لیتا.اس آیت میں ریا کی ممانعت کے ساتھ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ کے الفاظ اس لئے بڑھائے گئے ہیں کہ بعض دفعہ ایمان باللہ و الیوم الاٰخر کے ماتحت دوسروں کی تحریص کے لئے لوگوں کو دکھا کر اپنا مال خرچ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے.جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَھُمْ بِالَّیْلِ وَ النَّھَارِ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً فَلَھُمْ اَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلَاخَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَاھُمْ یَحْزَنُوْنَ (البقرۃ: ۲۷۵) یعنی جو لوگ رات اور دن پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے رہتے ہیں ان کے ربّ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے.اور انہیں نہ تو کوئی خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.اس آیت سے ظاہر ہے کہ بعض دفعہ دوسروں کو دکھانے کے لئے کام کرنا بھی موجب ثواب ہوتا ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ دوسروں کو نیکی کی تحریک ہو.لیکن اگر یہ نیت نہ ہو بلکہ ریاء فخر ومباہات کے لئے ہو تو ایسا فعل اعمال نیک کو اسی طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح ایک پتھر جس پر مٹی جمی ہوئی ہو جب اس پر بارش پڑے تو بجائے اس کے کہ اس پردانہ اُگے بارش مٹی کو بہا کر لے جاتی ہے اور دانہ اُگنے کا احتمال بھی باقی نہیں رہتا.اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اعلیٰ درجہ کا کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہو مگر کوئی تو اس لئے اس کا اظہار کرتا ہے کہ دوسروں پر فخر کرے اور کوئی اس نیت سے اظہار کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے.دیکھو! قرآن کریم ادھر تو کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جو ریا کے طور پر مال خرچ کرتے ہیں.مگر ادھر کہتا ہے.وَ اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحٰی: ۱۲) یعنی تمہیں خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہیں ان کا لوگوں میں اظہار کرو.اب یہ اظہار ریا نہیں بلکہ اس لئے ہے کہ لوگ بھی ان انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.پس ہر قسم کا اظہار ریا نہیں ہوتا.بلکہ بعض حالات میں نیکیوں کا اظہار ریا ہوتا ہے اور بعض دوسرے حالات میں ریاء نہیں ہوتا.مثلاً اگر ایک شخص اچھے کپڑے پہن کر اس لئے لوگوں میں جاتا ہے کہ وہ اسے بڑا مال دار سمجھیں تو یہ ریا ہے.لیکن اگر وہی شخص عید کے دن یا جمعہ کے دن عمدہ لباس پہن کر اس لئے نکلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو تو یہ ریا نہیں ہو گا.یا مثلاً کہیں بخار پھیلا ہوا ہو اور کسی کے پاس کونین ہو اور وہ لوگوں کو بتائے کہ میرے پاس کونین ہے تو یہ ریا نہیں ہو گا اور کوئی نہیں کہے گا کہ یہ اپنی عقل مندی جتا رہا ہے کہ میں نے پہلے سے ہی کونین کا انتظام کر رکھا تھا بلکہ ہر شخص اس کے اس اظہار سے خوش ہو گا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا.پس ریاء الناس اسی صورت میں گناہ ہے.جب ایسے شخص کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ ہو اور اس سے اجر لینا
Page 479
مقصود نہ ہو بلکہ محض لوگوں کو خوش کرنا مدّنظر ہو ورنہ ایمان باللہ و الیوم الاٰخر کے ساتھ لوگوں کو محض نیکی کی تحریص و ترغیب دلانے کے لئے اپنی بعض قربانیوں کا اظہار منع نہیں بلکہ ایک قابلِ تعریف فعل ہے.چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا ھِیَ وَ اِنْ تُخْفُوْھَا وَ تُؤْتُوْھَا الْفُقَرَآئَ فَھُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ (البقرۃ:۲۷۲) یعنی اگر تم علی الاعلان صدقے دو تو یہ بھی بہت اچھا طریق ہے اور اگر تم اپنے صدقات چھپا کر غریبوں کو دو تو یہ تمہارے نفس کے لئے زیادہ اچھا ہے.دوسرے معنے اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ریا کار کو خدا تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان نہیں ہوتا کیونکہ احسان وہی جتلاتا ہے جسے خدا تعالیٰ پر ایمان نہ ہو.اگر وہ اس نعمت کو خدا تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھے اور اسی سے اجر کی امید رکھے تو لوگوں کی واہ واہ کا وہ خواہش مند ہی کیوں ہو؟ اسی طرح اگر اسے یقین ہو کہ آخرت میں اجر ملے گا تو وہ کیوں اسی مسکین سے خدمت لے کر اپنا اجر پورا کرنا چاہے جس کی اس نے تھوڑی بہت مدد کی ہے؟ یہی حکمت ہے جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے منّ اور اذًی کے مقابلہ میں ریاء الناس اور لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ رکھا ہے.کیونکہ مَنّ ریاء الناس کے لئے کیا جاتا ہے.اور اَذًی سے مراد اس پر بوجھ رکھنا ہے اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کو اپنے صدقہ اور خیرات کی خدا سے جزا ملنے کی امید نہ ہو اور یوم آخر پر یقین نہ ہو.فَمَثَلُہٗ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْہِ تُرَابٌ.اب اللہ تعالیٰ ایک اور تمثیل بیان فرماتا ہے کہ خرچ کرنے کو تو ایک ریا کار بھی اپنا مال خرچ کرتا ہے مگر اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی پتھر ہو.اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو اور اوپر سے زور کی بارش برس جائے تو بجائے دانہ اُگنے کے وہ دُھل کر صاف ہو جائے گا.یہی اس شخص کا حال ہے کہ جب تک صدقہ نہیں دیا تھا تب تک تو اس کی کسی قدر اچھی حالت تھی لیکن صدقہ دےکر اور پھر مَنّ وَاَذًی سے کام لے کر یاریا کر کے ایک خطرناک بدی میں مبتلا ہو گیا اور یہ اچھا فعل بجائے مفید ہونے کے مضر ہو گیا.گویا تھوڑی بہت جو فصل اُگنے کی اُمید تھی وہ بھی جاتی رہی.وَ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کر نے کے لئے اور اپنے آپ کو مضبوط کر نے تَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کے( خرچ کی )حالت اس باغ کی حالت کے مشابہ ہے جو اونچی جگہ پر ہو
Page 480
فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ١ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ١ؕ وَ اور اس پر تیز بارش ہو ئی ہو.جس (کی وجہ )سے وہ اپنا پھل دو چند لایا ہو.اور (اس کی یہ کیفیت ہو کہ) اگر اس پر اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۰۰۲۶۶ زور کی بارش نہ پڑے تو تھوڑی سی بارش ہی (اس کے لئے کافی ہو جائے )اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے.حل لغات.اِبْتِغَآءَ یہ حال ہے اور اس کے معنے ہیں ’’چاہتے ہوئے‘‘.لیکن یہ مفعول لہٗ بھی ہو سکتا ہے.اس صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہنے کے لئے.(اقرب) تَثْبیْتًا یہ بھی حال ہے.اس کے معنے ہیں اپنی جانوں کو مضبوط کرتے ہوئے.یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مِنْ کے معنے ل کے ہوں.چنانچہ کہتے ہیں.فَعَلْتُ ذَالِکَ کَسْرًا مِّنْ شَھْوَتِیْ یعنی میں نے اپنی شہوت توڑنے کے لئے فلاں کام کیا.اسی طرح یہاں مِنْ کے معنے ہیں کہ اپنے نفسوں کی ثابت قدمی کے لئے.تثبیت کے ایک معنے ہیں کسی چیز کو گاڑ دینا.نفس کو گاڑ دینے کے معنے یہ ہوں گے کہ جس بات پر اسے قائم کریں اس پر وہ مضبوط ہو جائے.اس میں پختگی پیدا ہو جائے.استقلال اور مردانگی آجائے.(اقرب) رَبْوَۃٌ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْاَرْضِ.زمین کا وہ حصہ جو بلند ہو.(اقرب) وَابِلٌ اَلْوَابِلُ اَ لْمَطَرُ الشَّدِیْدُ وَالضَّخِیْمُ الْقَطَرِ.موٹے موٹے قطرات والی سخت زور کی بارش.اٰتَتْ (۱) دِیئے (۲) لائے.(اقرب) ضِعْفَیْن (۱) بڑھا چڑھا کر (۲) دوہرے دوہرے کر کے.بعض جگہ کسی اسم کے دُہرانے کی بجائے اسے تثنیہ کر دیتے ہیں.اصل میں ضِعْفًا وَ ضِعْفًا تھا اس کی بجائے ضِعْفَیْنِ کر دیا.(اقرب) اَلطَّلُّ اَضْعَفُ الْمَطَرِ کمزور ہلکی بارش اَلنَّدٰی.شبنم.اوس.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے.وہ لوگ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لئے خرچ کرتے ہیں.ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہو اور وہ اونچی جگہ پر ہو.اس جگہ رَبْوَۃ کا لفظ اس لئے استعمال فرمایا کہ اونچی جگہ ہمیشہ سیلاب سے محفوظ رہتی ہے.جب بارش ہوتی ہے تو نشیب زمین میں پانی ٹھہر جاتا ہے جس سے کھیتوں کو نقصان پہنچتا ہے مگر اونچی جگہ محفوظ رہتی ہے.ایسی جگہ پر تیز بارش ہو تو کھیتی بہت پھل
Page 481
دیتی ہے.لیکن اگر زیادہ بارش نہ ہو تب بھی تھوڑی بارش سے ہی پھل پیدا ہو جاتا ہے اور وہی اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے.اس تمثیل میں بتایا کہ سچے مومن کا دل ایک باغ کی طرح ہوتا ہے جس میں نیک اعمال کے ہرے بھرے پودے کھڑے ہوتے ہیں.جب وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو خواہ وہ صدقہ بارش کی طرح نہ ہو بلکہ معمولی شبنم کی طرح ہو تب بھی وہ اس نیکی کے بابرکت نتائج حاصل کر لیتا ہے.چونکہ اس قسم کے صدقات دینے والوں میں اکثر غرباء ہوتے ہیں.ان کو خیال ہو سکتا تھا کہ ہمارے صدقے وابل کہاں کہلا سکتے ہیں؟ اس لئے فرمایا کہ وابلؔ نہیں تو طلّؔ بھی اس کھیتی کو بڑھادے گی.گویا امیر آدمی کے صدقہ کو وابلؔ اور غریب آدمی کے صدقہ کو لَایَجِدُوْنَ اِلَّا جُھْدَھُمْ (التوبة:۷۹) کے ماتحت طلّ قرار دیا ہے.مگر چونکہ ان کے دل میں اخلاص اور تقویٰ ہوتا ہے اس لئے فرمایا کہ وہ جو کچھ خرچ کریں گے اس سے بھی ان کی کشتِ عمل خوب ہری بھری ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جزا دل کے اخلاص پر مبنی ہوتی ہے نہ کہ مال کی مقدار اور کمیت پر.صحابہ کرامؓ میں دونوں قسم کے لوگ موجود تھے.ایک غربت کی وجہ سے تھوڑا خرچ کرنے والے.اور دوسرے بہت خرچ کرنے والے.جو لوگ تھوڑا خرچ کرنے والے تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری قربانیاں تو وابل نہیں کہلا سکتیں.اس لئے ان کی خاطر فرمایا کہ طل ہی سہی.وہ تمہیں وابل جیسا فائدہ ہی دے دے گی.وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی اصل حقیقت دیکھتا ہے اس کی ظاہری شکل نہیں دیکھتا.اس لئے تھوڑا دینے والا گو دوسرے کے مقابلہ میں کم دیتا ہے مگر چونکہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے اس لئے اس کو اس طلّ سے ہی وابل والا فائدہ پہنچ جاتا ہے.یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی دو اغراض بیان فرمائی ہیں.اوّل ابتغاء مرضات اللہ دوم تَثْبِیْتًا مِّنْ اَنْفُسِھِمْ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول اور قوم کی مضبوطی.کیونکہ صدقات کے نتیجہ میں غرباء کو ترقی کے مواقع میسر آجاتے ہیں اور وہ بھی اپنی قوم کا ایک مفید جزو بن جاتے ہیں.جس قوم کے افراد گرے ہوئے ہوں وہ قوم بھی یقینی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتی کیونکہ گرے ہوئے افراد اس کے لئے بوجھ بن جاتے ہیں اور وہ ترقی کی طرف اپنا قدم بڑھانے سے قاصر رہتی ہے.اسی لئے یورپین قومیں جن کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی محض اس لئے صدقہ و خیرات کرتی رہتی ہیں کہ قوم کے غرباء کی ترقی سے خود قوم بڑھتی اور ترقی کرتی ہے.غرض صدقہ کی اسلام نے دو اغراض بتائی ہیں.اوّل اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول جو سب سے بڑی اور حقیقی غرض ہے.دوم قوم کی مضبوطی.کیونکہ غرباء کی مدد درحقیقت اپنی مدد ہوتی ہے.
Page 482
دوسرے معنے اس کے یہ بھی ہیں کہ جب مومن کمزور اور بے سہارا لوگوں کی امداد کے لئے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا اور ان کی مضبوطی اور ترقی کے سامان پیدا کرتا ہے.اسی نکتہ کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی یہ حدیث اشارہ کرتی ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے مشکل اوقات میں اس کی تائید فرماتا ہے.(مسلم کتاب البر و الصلة و الادب.باب تحریم الظلم) (۳) پھر روحانی طور اس انفاق کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ دین میں مضبوط ہوتا جاتا ہے اسی وجہ سے میں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بارہا کہا ہے کہ جو شخص دینی لحاظ سے کمزور ہو وہ اگر اور نیکیوں میں حصہ نہ لے سکے تو اس سے چندہ ضرور لیا جائے کیونکہ جب وہ مال خرچ کرے گا تو اس سے اس کو ایمانی طاقت حاصل ہو گی اور اس کی جرأت اور دلیری بڑھ جائے گی اور وہ دوسری نیکیوں میں بھی حصہ لینے لگ جائے گا.یہ معنے اس صورت میں ہوں گے جبکہ تَثْبِیْتًا کو حال بنایا جائے.اگر اسے مفعول لِاَجْلِہٖ قرار دیں تو پھر پہلے دو معنی ہی ہوں گے.اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو.تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ١ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ١ۙ وَ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں.(اور) اسے اس میں سے ہر قسم کے پھل ملتے (رہتے) ہوں.اَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ١۪ۖ فَاَصَابَهَاۤ اِعْصَارٌ اور اسے بڑھاپے نے بھی آ پکڑا ہو.اور اس کے چھوٹے (چھوٹے) بچے ہوں.پھر اس باغ پر ایک ایسا بگولا چلے فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ١ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ جس میںآگ (کی سی گرمی )ہو اور وہ (باغ) جل جائے.(دیکھو )اللہ (تعالیٰ) تمہارے (فائدہ کے) لئے اس
Page 483
تَتَفَكَّرُوْنَؒ۰۰۲۶۷ طرح اپنے احکام بیان کر تا ہے تاکہ تم فکر (سے کام لیا )کرو.حلّ لُغات.نَخِیْلٌ نَخْلٌ کی جمع ہے.اس کے معنے کھجوریں یا کھجوروں کے باغ کے ہیں.(اقرب) اَعْنَابٌ عِنَبٌ کی جمع ہے اور اس کے معنے انگور ہیں.(اقرب) اَلْکِبَرُ کَبُرَ الرَّجُلُ اَوِالدَّآبَّۃُ کے معنے ہیں طَعَنَ فِی السِّنِّ.آدمی یا جانور بڑا ہو گیا.(اقرب) اِعْصَارٌ ایسی ہوا کو کہتے ہیں جو زمین سے مٹی اُڑاتی ہوئی ستون کی طرح آسمان کی طرف چلی جاتی ہے.ہماری زبان میں ایسی ہوا کو بگولا کہتے ہیں.یہ لفظ ہمیشہ سختی کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے.عرب لوگ کہا کرتے ہیں.اِنْ کُنْتَ رِیْحًا فَقَدْ لَاقَیْتَ اِعْصَارًا.اگر تو تیز ہوا ہے تو جس سے تجھے پالا پڑا ہے وہ بگولا ہے.گویا آج تیرا واسطہ سخت شخص سے پڑا ہے.بگولہ میں سخت تیزی کی وجہ سے ایسی آگ پیدا ہو جاتی ہے جس سے جنگل کے جنگل جل جاتے ہیں.(اقرب) تفسیر.اب اللہ تعالیٰ ایک اور تمثیل کے ذریعے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پرروشنی ڈالتا ہے.دنیا میں اگر کسی کے پاس تھوڑا سامال ہو اور وہ ضائع ہو جائے تو اس کا بھی اسے افسوس ہوتا ہے.لیکن اگر کسی کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے ساتھ نہریں بہتی ہوں اور اسے اس باغ میں سے ہر قسم کے پھل ملتے رہتے ہوں.اور وہ خود بوڑھا ہو چکا ہو اور اسے زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ ہو.اس کے بچے چھوٹی عمر کے ہوں جن سے کمائی کی اُمید نہ ہو.تو کیا اس کا دل چاہتا ہے کہ ایک بگولا زور سے آئے اور اس کے باغ کو جلادے.بگولا اس لئے فرمایا کہ ایک تو وہ سخت تیز ہوتا ہے.دوسرے اچانک آتا ہے اور اس میں بوجہ تیزی کے آگ پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ بہت جگہ جہاں جنگل زیادہ ہوتے ہیں یہ نظارہ دیکھنے میں آتا ہے.اگر تھوڑا سا مال ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ خیر تھوڑا سامال تھا اگر ضائع ہو گیا تو کوئی بڑی بات نہیں یا اگر میرے کام آتا تو کب تک آتا؟ آخر اس نےختم ہی ہونا تھا.پھر اگر بوڑھا نہ ہوتا تو خیال کر سکتا تھا کہ میری زندگی میں بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنے لئے جائیداد پیدا کر لیں گے.لیکن اگر مال بھی زیادہ ہو.خود بھی بوڑھا ہو اور پھر اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں تو وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا مال تباہ ہو جائے اور کسی حادثہ سے اس کی تمام جائیداد جل کر فنا ہو جائے.اور اگر کسی حادثہ سے اس کی تمام جائیداد جل کر تباہ ہو جائے تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اسے کس قدر صدمہ
Page 484
ہو گا! یہی حالت قیامت کے دن ان لوگوں کی ہو گی جنہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال خرچ نہیں کئے.اس وقت ان کے پاس کوئی مال نہیں ہو گا جسے وہ پیش کر سکیں اور نہ اولاد وغیرہ کام آئے گی اس لئے فرمایا کہ تم اپنا انجام سوچ لو! آج تم اپنے لئے سب کچھ کر سکتے ہو.مگر آخرت میں کچھ نہیں کر سکو گے.اگر آج تم اپنامال خرچ کرو گے تو یہ مال تمہارے لئے وہاں ذخیرہ کے طور پر جمع رہے گا اور تم اس سے فائدہ اٹھا سکو گے ورنہ تم ہلاک ہو جائو گے.ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ کے الفاظ خاص طور ہوشیار کرنے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ جب تم اپنے بچوں کے لئے دنیا کی محدود زندگی میں بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ ایسی بے بسی کی حالت میں رہ جائیں تو تمہاری اپنی جان جو کہ اگلے جہان میں ایک بچہ کی حالت سے بھی زیادہ نازک حالت میں ہو گی کیوں توجہ کی مستحق نہیں.تم سوچواور غور کرو کہ ایمان کی نعمت یا رضائے الٰہی جیسی نعمت جو ایسے وقت میں کام آنی ہے.جب بچہ جتنی طاقت بھی تمہارے اندر نہیں ہو گی اور خود تمہارے کام آنی ہے اس کو اس بے پروائی سے ضائع کر دینا کہاں کی عقلمندی ہے؟ پس تم ابھی سے ہوشیار ہو جائو اور موت سے پہلے اپنے لئے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لو.يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ اے ایمان دارو! جو کچھ تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں اور (نیز )اس میں سے جو ہم نے مِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ١۪ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ تمہارے لئے زمین سے نکالا ہے (اللہ کی راہ میں حسب توفیق )خرچ کرو.اور ناکارہ چیز کو اور جس میں سے تم مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ١ؕ خرچ (تو)کر تے ہو مگر خود تم سوائےاس کے کہ اس (کے قبول کرنے )میں چشم پوشی سے کام لو اسے ہرگز قبول نہیں وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ۰۰۲۶۸ کرتے.(صدقہ کے لئے )بالارادہ نہ چنا کرو.اور جان لو کہ اللہ( تعالیٰ بالکل) بے نیاز (اور) بہت ہی حمد کا مستحق ہے.حل لغات.اَلْخَبیْثُ اَلنَّجَسُ.اَلرَّدِّیُّ.اَلْمَکْرُوْہُ (اقرب) یعنی خبیث ہر ناپاک.ردّی اور
Page 485
ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں.تَیَمُّمٌ تَیَمَّمَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں تَعَمَّدَہٗ جان بوجھ کر اور نیت اور ارادہ کے ساتھ کسی چیز کو اختیار کیا.پس لَاتَیَمَّمُوْا کے یہ معنے ہیں کہ تم قصداً اور ارادۃً ناکارہ چیز کو صدقہ کے لئے مت چنو.(اقرب) تُغْمِضُوْا اَغْمَضَ عَیْنَیْہِ کے معنے ہیں.اَطْبَقَ اَجْفَانَھُمَا.اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں.اور اَغْمَضَ عَنِ الشَّیْءِ کے معنے ہیں تَجَاوَزَہٗ کسی چیز سے تجاوز کیا.اور اَغْمَضَ عَلٰی کَذَا کے معنے ہیں.تَحَمَّلَہٗ وَرَضِیَ بِہٖ اسے برداشت کر لیا اور اس پر راضی ہو گیا.(اقرب) جب یہ لفظ بغیر صِلہ کے آئے تو اس کے معنے بند کر لینے کے ہوتے ہیں.اور جب عَنْ کے ساتھ آئے تو اغماض کے معنے ہوتے ہیں.یہاں یہ تینوں معنے ہو سکتے ہیں.(۱) یعنی تم اپنی آنکھیں بندکر کے لے لو (۲) یا تم اس میں تجاوز سے کام لو.یعنی دوسرے کی اس حرکت کو تم نظر انداز کردو.اور اسے لے لو.(۳) یا یہ کہ تم دوسرے کی خاطر اسے برداشت کر لو.تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ دو اس مال میں سے دو جو تمہارا کمایا ہوا ہے اور اچھا مال ہے.یہ نہیں کہ دوسروں کے اموال پر ناجائز تصرف کر کے ان کو خرچ کرنے لگ جائو.کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے دل میں غریبوں کی امداد کاجوش پیدا ہوتا ہے.تو وہ ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر انہیں جو کچھ ملتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں.وہ لوگ جو فلسفہ اخلاق سے واقف نہیں ہوتے بالعموم ایسے ڈاکوئوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکو بڑا اچھا ہےکیونکہ وہ غریبوں کی خوب مدد کرتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غریبوں کی مدد کرنے کا کوئی طریق نہیں کہ ڈاکہ ڈالا اور دوسرں کا مال چھین کر غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی جائز کمائی میں سے جتنا دے سکتے ہو دو اور باقی کام خدا تعالیٰ پر چھوڑ دو.لوگوں کا مال لوٹ کر غرباء کی امداد کرنا تو حلوائی کی دوکان پر دادا جی کے فاتحہ کا مصداق بننا ہے.اگر تمہارے نزدیک غرباء زیادہ ہیں تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں.تم جتنا دے سکتے ہو دو اور باقی کام خدا تعالیٰ کے سپرد کردو.اس جگہ مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ سے یہ مراد نہیں کہ مومنوں کی کمائی میں کچھ پاک مال ہوتا ہے اور کچھ ناپاک اور انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صرف پاک مال خرچ کیا کریں.ناپاک مال خرچ نہ کیا کریں.بلکہ یہ الفاظ مَاکَسَبْتُمْ کی صفت ِ حسنہ کے اظہار کے لئے استعمال کئے گئے ہیں اور مراد یہ ہے کہ تم نے جو کچھ کمایا ہے وہ طیب ہی ہے لیکن ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اس طیّب مال کا بھی (جس میں ہر قسم کا مال اور علم بھی شامل ہو سکتا ہے) ایک
Page 486
حصہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو.گویا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ فرما کر مومنوں کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ ان کا مال ہمیشہ طیب اور پاک ہی ہوتا ہے.ناپاک مال کی اس میں ذرا بھی آمیزش نہیں ہوتی.دوسرے یہاں طیب حرام کے مقابلہ میں نہیں بلکہ خبیث کے مقابلہ میں آیا ہے.اور مطلب یہ ہے کہ اَنْفِقُوْا میں صدقہ دینے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ تب پورا ہو گا جب تم اپنے اچھے اور مرغوب مال میں سے خرچ کرو گے.یوں مستعمل اشیاء بھی غرباء کو دی جا سکتی ہیں اور ان کا دینا ہرگز منع نہیں.مثلاً انسان اگر کسی کو پرانا کپڑا دے دے جس سے دوسرا شخص فائدہ اٹھالے تو یہ ناجائز نہیں بلکہ یہ فعل اسے ثواب کا مستحق بنائے گا.مگر اللہ تعالیٰ نے اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ میں صدقہ دینے کا جو حکم دیا ہے وہ اس سے عہدہ بر آنہیں ہو گا.وہ اس حکم سے اسی وقت عہدہ برآ ہو گا.جب وہ اس چیز میں سے دے جو اس کے کام کی ہے.یعنی اعلیٰ درجہ کا اور اچھا مال دے تاکہ اس کی قربانی زیادہ بلند شان رکھنے والی ہو.پھر فرمایا وَ مِمَّا اَخْرَجْنَا لَکُمْ مِنَ الْاَرْضِ تم اس میں سے بھی خرچ کرو جوہم نے تمہارے لئے زمین میں سے نکالا ہے.درحقیقت دنیا میں دو ہی طرح مال حاصل ہوتا ہے.ایک تو تجارت اور ملازمت وغیرہ کے ذریعہ.دوسرے ان ذخیروں کے ذریعہ جو خدا تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھے ہیں.او رانسان کوشش کر کے ان کو نکالتا ہے.جیسے کھیتوں دفینوں اور کانوں وغیرہ سے انسان کو آمدنی ہوتی ہے.پس مِنَ الْاَرْضِ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں.صرف زراعت مراد نہیں.اسی طرح نباتات وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں.غرض دو قسمیں بتا کر ان دونوں کی طرف اشارہ کر دیا اور بتایا کہ خواہ تم ملازمت تجارت اور صنعت وحرفت وغیرہ کے ذریعہ روپیہ کمائو.خواہ زمینی ذخائر اور معدنیات سے فائدہ اٹھائو.تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے تمام اموال کا ایک حصہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہو.وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ.یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلق اَلْـخَبِيْثَ کا لفظ رکھا ہے.اور یہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس کے لئے خبیث ہو.اس وجہ سے اس کے کئی معنے ہو سکتے ہیں.(۱) ایک معنے تو یہ ہیں کہ وہ چیز جو فی نفسہٖ بُری اور ناقابلِ استعمال ہو نہ یہ کہ اضافی طور پر.یعنی جو چیز کسی فرد کے لئے بھی قابلِ استعمال نہ ہو وہ کسی کو نہ دو.ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز دینے والے کے کام کی تو نہ ہو مگر لینے والے کے کام کی ہو.(۲) ایسی چیز نہ دو کہ جسے تم دینے لگے ہو وہ اسے ناپسند کرتا ہو یا اسے مکروہ نظر آئے.اس میں بتایا کہ جسے تم کوئی چیز دو اس کے احساسات کا بھی خیال رکھ لیاکرو تاکہ اس کا دل میلا نہ ہو یا ایسی چیز نہ ہو جو اس کے کام کی نہ ہو.(۳) تیسرے معنے تیمم کے لفظ سے یہ پیدا ہوتے
Page 487
ہیں کہ تلاش کر کے ناپسندیدہ اور ناکارہ چیزیں مت دو.یعنی یہ دیکھ کر کہ فلاں چیز تو میرے کسی کام کی نہیں اس لئے دے دوں درست نہیں.وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِیْہِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِیْہِ.فرمایا ایسی چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں مت دو کہ اگر خود تمہیں وہی چیز ملے تو تم شرم کے مارے تو لےلو مگر یوں نہیں لے سکتے.وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ.فرماتا ہے.یہ صدقات تمہارے ہی فائدہ کے لئے ہیں.اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی احتیاج نہیں.اگر تم اس کے راستہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہو یا اس کے بندوں کو دیتے ہو تو درحقیقت خدا تعالیٰ کو ہی دیتے ہو.اس لئے تم اس کے بندوں کو صدقہ دیتے وقت خدا تعالیٰ کی عظمت کو ملحوظ رکھو.جب تم دنیوی لوگوں سے معاملہ کرتے وقت ان کی شان کو ملحوظ رکھتے ہو حالانکہ وہ بہت ہی معمولی درجہ کے ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے جب تم صدقہ دیتے ہو تو اس کی شان کو کیوں ملحوظ نہیں رکھتے؟ وہ تو غنی بھی ہے اور حمید بھی.اسے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں.بلکہ تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے اور پھر وہ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے.اس لئے تم اس کے بندوں سے اچھا سلوک کرو تا وہ بھی تم سے اچھا سلوک کرے.اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ١ۚ وَ اللّٰهُ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے.اور تمہیں بے حیائی کی تلقین کرتاہے.اور اللہ اپنی طرف سے ایک يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا١ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌۖۙ۰۰۲۶۹ بڑی بخشش اور بڑے فضل کا تم سے وعدہ کر تا ہے.اور اللہ بہت وسعت دینے والا (اور )بہت جاننے والا ہے.حلّ لُغات.یَعِدُکُمْ وَعَدَہٗ کے معنے اچھا وعدہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور بُرا وعدہ کے بھی.اسی طرح اَوْعَدَ کے معنے بھی دونوں ہوتے ہیں.خیر کے بھی اور شر کے بھی.لیکن اَوْعَدَ کا کثیر استعمال شر کے متعلق ہے جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو.اسی طرح وعدہ کا کثیر استعمال خیر کے لئے ہے جبتک کہ کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو.اور قرینہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ مفعول بھی بیان کر دیتے ہیں اس سے خیر یا شر کا پتہ لگ جاتا ہے (اقرب) مثلاً کہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ دس کوڑوں کا میں وعدہ کرتا ہوں.تو اس صورت میں اس کے معنے شرکے ہوں گے.یہاں چونکہ فقر کا ذکر آتا ہے اس لئےاس کے معنے شر ہی کے ہیں.اور وَعَدَ کے معنے ڈرانے کے ہیں.
Page 488
فَحْشَآءَ کے معنے ہیں ہر وہ بدی جو نمایاں ہو جائے.اسی طرح فحشاء بخل کو بھی کہتے ہیںـ.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے.خواہ یہ ڈرانا مالی قربانی کے متعلق ہو یا جانی قربانی کے متعلق.یا اور سینکڑوں قسم کی قربانیوں کے متعلق.وہ کہتا ہے کہ اگر تم مال دو گے تو تمہاری ضروریات کے لئے کچھ نہیں رہے گا.تم تنگ دست ہو جائو گے اور لوگوں سے مانگتے پھروگے.یا جان پیش کرو گے تو تباہ ہو جائو گے مگر اس کے ساتھ ہی اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر بے حیائی کے کام ہوں تو شیطان انسان کو بلا دریغ اپنا سارا روپیہ لٹا دینے کی ترغیب دیتا ہے.گویا نیکی کی راہ میں تو وہ ایک ناصح مشفق بن کر کھڑا ہو جاتا ہے.اور بدی کی راہ میں دلیری سے قدم آگے بڑھانے کی تلقین کرتا ہے.غرض قربانی کرنے کو تو ایک مومن بھی کرتا ہے اور کافر بھی.مگر مومن کی قربانی خدا کے لئے ہوتی ہے اور کافر کی قربانی ایسے کاموں کے لئے ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہوتے ہیں.دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ شیطان انسان کے ساتھ وعدہ تو راحت و آرام اور دولت و آسائش کا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے رستہ میں اپنا مال خرچ نہ کرو گے تو تم بڑے مال دار ہو جائو گے.بڑی بڑی کو ٹھیاں بنا لو گے اور ہر قسم کے سامان جمع کر لو گے.مگر اس کا نتیجہ فقر ہوتا ہے کیونکہ جو قوم غرباء کی طرف توجہ نہیں کرتی اور صرف اپنے عیش و آرام کا خیال رکھتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے.جیسا کہ مردہ قوموں کی حالت سے ظاہر ہے.اسی لئے فرمایا کہ شیطان تم سے ایسی باتوں کا وعدہ کرتا ہے جو بظاہر تو بھلی معلوم ہوتی ہیں مگر ان کا انجام فقر یعنی تباہی اور بربادی اور رسوائی ہوتا ہے.وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ اور جن کاموں کا حکم دیتا ہے ان کا عیب کھلا اور ظاہر ہوتا ہے.فحش ہر ایسی بدی کو کہتے ہیں جس کی بُرائی ظاہر ہو…اسی طرح فحش بخل کو بھی کہتے ہیں.اس لحاظ سے اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے حالانکہ بخل ایک ناپسندیدہ امر ہے اور عرب لوگ تو خصوصیت سے بخل کو سخت بُرا سمجھتے تھے یا یہ کہ وہ ہمیشہ بدی کا ہی حکم دیتا ہے.گویا عملاً بھی وہ بُری بات ہوتی ہے اور عزت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہوتی ہے.اور یہی دو باتیں انسان کو کسی کام سے روکتی ہیں.انسان یا عزت کو دیکھتا ہے یا فائدہ کو دیکھتا ہے.وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا.اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے.یعنی تمہاری کمزوریوں کی پردہ پوشی کرنے اور عیوب کو مٹا دینے کا اور پھر پہلے سے بھی زیادہ دینے کا.یہاں اگر مغفرت کو عام رکھا جاتا تو یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ اس سے مراد بندوں کا ایک دوسرے کی کمزوری کو نظرانداز کرنا ہے مگرمَغْفِرَةً مِّنْهُ فرما کر اس طرف
Page 489
اشارہ کیا کہ یہ مغفرت اس کی طرف سے ہو گی اور پھر یہی نہیں کہ وہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے بلکہ وہ فضل کا بھی وعدہ کرتا ہے.یعنی اس بات کا بھی کہ وہ تمہیں مزید ترقی دے گا اور تمہارے لئے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دے گا.اگر پہلی آیت میں یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ کے معنے افلاس اور محتاجی سے ڈرانے کے لئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ شیطان تو فقر کو بڑا سمجھتا ہے اور خدا تعالیٰ گناہ کو.اس لئے وہاں فقر کو پہلے رکھا اور یہاں مغفرت کو.اس طرح رحمانی اور شیطانی سلسلوں میں جو اشیاء کی عظمت کا فرق ہے اس کو ظاہر کر دیا.حضرت خلیفۂ اول رضی اللہ عنہ اَلشَّیْطٰنُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ کی مثال میں اودھ کی ریاست کی مثال سنایا کرتے تھے کہ جب انگریزوں کا اس سے بگاڑ شروع ہوا تو انہوں نے ریاست کے ان تمام لوگوں کو جن کا روپیہ کلکتہ کے بنکوں میں جمع تھا نوٹس دے دیا کہ اگر تم ہمارے مقابلہ میں اُٹھے تو تمہارا تمام روپیہ ضبط کر لیا جائے گا.اس پر وہ اپنے فقر کے خیال سے چپ کر کے بیٹھ گئے اور انگریز نواب کو گرفتار کر کے لے گئے.لیکن یورپین اقوام چونکہ قربانی کی عادی ہیں اس لئے وہ اس قسم کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتیں.چنانچہ پہلی جنگ عظیم میں کروڑوں روپیہ جرمنی کا انگریزوں کے ہاں تھا اور انگریزوں کا کروڑوں روپیہ جرمنی میں تھا.لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ کی گئی اور پورے زور سے لڑائی شروع کر دی گئی.تو زندہ رہنے والی قومیں جانتی ہیں کہ روپیہ خرچ کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے اس لئے وہ خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتیں لیکن جو قومیں روپیہ جمع رکھتی ہیں اور غرباء پر خرچ نہیں کرتیں وہ نقصان اُٹھاتی ہیں.یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقرسے ڈراتا ہے حالانکہ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم تباہ ہو جائو گے.اور جب تم اپنے غریب بھائیوں سے برا سلوک کروگے تو دشمن تک کہیں گے کہ یہ لوگ بڑے پست فطرت ہیں.انہوں نے غریبوں کا خیال تک نہ رکھا.لیکن اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم صدقہ کروگے تو اس کے نتیجہ میں تمہیں مغفرت حاصل ہو گی.یعنی جب تم غرباء کو اُبھاروگے تو تمہارے اپنے عیب بھی چھپ جائیں گے کیونکہ وہ شخص جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو ا س میں اگر کوئی عیب بھی ہو تو لوگ اسے چھپا لیتے ہیں اور اگر یہ مطلب لیا جائے کہ وہ جن باتوں کا وعدہ کرتا ہے وہ آخر فقر پیدا کرتی ہیں تو اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کا پہلا نتیجہ تو یہ ہو گا کہ جب تم لوگوں کے عیوب ڈھانکو گے تو وہ تمہارے عیوب ڈھانکے گا.گویا اس ذریعہ سے تم خدا کے حضور میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی نیکی حاصل کروگے اور دوسرا نتیجہ یہ ہو گا کہ یہاں بھی تمہارے مال میں زیادتی ہو گی.کیونکہ قومی اخراجات میں حصہ لینے یا غرباء قوم کو بڑھانے اور ترقی دینے سے قومی طاقت ترقی کرے گی اور آخر تم کو مالی فائدہ بھی پہنچے گا اور اس خرچ کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں
Page 490
اگلے جہان میں جو کچھ دے گا اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا.وَاللّٰہُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ میں بتایا کہ اگر تم خدا تعالیٰ کے احکام کی اتباع کروگے تو اس کے پاس سب کچھ ہے.وہ تمہیں بہت کچھ دے گا بلکہ تم اس کے وعدۂ فضل و مغفرت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اور نہ وعدۂ فضل کے معنوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہو او رپھر وہ عَلِیْمٌ ہے.تمہارے ہر ایک کام سے واقف ہے.اس سے کچھ پوشیدہ نہیں.وہ تمہاری ان طریقوںسے مدد کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتے.اِن آیات پر غور کرو اور دیکھو کہ ان میں الفاظ کی ترتیب کیسی اعلیٰ درجہ کی رکھی گئی ہے.پہلے حصہ میں فقر کو پہلے رکھا ہے اور فحشاء کو بعد میں اور دوسرے حصہ میں پہلے مغفرت کو رکھا ہے اور بعد میں فضل کو.حالانکہ ظاہر کے لحاظ سے فضل کو مغفرت سے پہلے رکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ فقر کے مقابلہ میں ہے.اور مغفرت کو بعد میں رکھنا چاہئے تھا.کیونکہ یہ فحشاءؔ کے مقابلہ میں ہے.اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو ظاہری ترتیب ہوتی ہے اور ایک روحانی ترتیب ہوتی ہے.یہ ظاہری ترتیب ہے.یعنی شیطان پہلے فقرؔ سے ڈراتا ہے اور پھر فحشاءؔ کا حکم دیتا ہے جس کے نتیجہ میں پہلے کسی قوم کو ذلّت پہنچتی ہے اور پھر ساری دنیا میں اس کی بدنامی ہوتی ہے.اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے پہلے مغفرت کا سلوک ہوتا ہے اور پھر فضل کا.جب اپنی قوم کے غرباء سے اچھا سلوک کیا جائے گا تو اس کے نتیجہ میں لازماً مغفرتؔ ہوگی اور پھر اس کے بعد فضل کا نزول ہو گا.یہ تو اس ترتیب کی ظاہری وجہ ہے.روحانی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے نزدیک عزت و آبروکی نسبت مال زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس لئے اس کے ذکر میں مال کو مقدم رکھا اور عزت کو بعد میں لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک مال کی نسبت عزت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس لئے اس نے مغفرت کو پہلے رکھا اور فضل کو بعد میں یعنی پہلے نیک نامی کو مدّنظر رکھا اور بعد میں مال کو.دوسرے اس میں بتایا ہے کہ سچے اور جھوٹے مذہب میں یہ فرق ہے کہ جھوٹے مذہب میں دنیا مقدم رکھی جاتی ہے اور سچے مذہب میں دین کو.جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ کوئی شخص ردّی چیز اس لئے دیتا ہے کہ اچھی چیز دینے سے فقر پیدا ہو جائے گا اور کوئی عمدہ اور اعلیٰ چیز اس لئے دیتا ہے کہ اس کا ایمان ترقی کرے گا.
Page 491
يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ١ۚ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ وہ جسے چاہتاہے حکمت عطاکر تاہے.اور جسے حکمت عطا کی گئی ہو تو (سمجھو )کہ اسے ایک بہت ہی نفع رساں اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا١ؕ وَ مَا يَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ۰۰۲۷۰ چیز مل گئی.اور (یاد رہے کہ) عقلمندوں کے سوا نصیحت بھی کوئی حاصل نہیں کیا کرتا.حل لغات.اَلْبَابُ اَللُّبُّ کے معنے ہیں خَالِصُ کُلِّ شَیْءٍ ہر چیز کا خالص حصہ(۲) اَلْعَقْلُ.عقل (۳) اَلْخَالِصُ مِنَ الشَّوَائِبِ اَوْمَازَکٰی مِنَ الْعَقْلِ فَکُلُّ لُبٍّ عَقْلٌ وَلَاعَکْسَ.یعنی لُبّ اس عقل کو کہتے ہیں جو خالص ہو اور ہر عقل خالص نہیں ہوتی او رنہ نقصوں سے پاک ہوتی ہے پس عقل عام ہے اورلُبّ خاص.ہرلُبّ عقل ہے مگر ہر عقللُبّ نہیں کہلا سکتی.(۴) لُبّ مغز کو بھی کہتے ہیں.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے.یہ قومی ترقیات کے گُر ہیں جو ہمارا رسول تم پر ظاہرکر رہاہے.کیونکہ یہ دعائے ابراہیمی کا مصداق ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے خدا! تو ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو یُعَلِّمُھُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ کا مصداق ہو.یعنی لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائے اور قومی ترقی کے راز ان پر ظاہرکرے.پس یاد رکھو! کہ حکمت کا سکھایا جانا کوئی معمولی بات نہیں.جسے حکمت کی کوئی ایک بات بھی ملے.اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کثیر حاصل ہوئی ہے یعنی عمل نیک بھی اچھی شے ہے.مگر نیکیوں میں ترقی کرنے کے گُر اور کاموں کی حکمتیں معلوم ہو جائیں تو یہ ایک بڑی خیر ہے.بلکہ یوں سمجھو کہ گویا ہیروں اورجواہرات کی ایک کان مل گئی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تمام اچھی تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہیں.لیکن اگر اس کے احکام کی حکمت سمجھ میں آجائے تو انسان کا جوشِ عمل بڑھ جاتا ہے.اور ناواقفیت کی صورت میں سستی ترقی کرتی ہے.پس احکام کی حکمتوں کا علم بڑی مفید چیز ہے مگر فرماتا ہے کہ لوگ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے صرف وہی لوگ جن کی نظرذاتی فوائد پر نہیں ہوتی بلکہ ساری قوم کے فوائد پر ہوتی ہے وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
Page 492
وَ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اور جو کچھ بھی تم (خدا کے لئے) خرچ کرو.یا جو کچھ بھی تم نذر مانو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ١ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ۰۰۲۷۱ (وہ اس کا نیک بدلہ دے گا) اور ظالموں کا کوئی بھی مدد گار نہیںہوگا.حلّ لُغات.نَذَرْتُمْ نَذَرَ کے معنے ہیں.(۱) اَوْجَبَ عَلٰی نَفْسِہٖ مَالَیْسَ بِوَاجِبٍ.اس نے اپنے نفس پر کوئی ایسی چیز واجب کر لی جو اس پر واجب نہ تھی.(۲) اَوْجَبَ عَلٰی نَفْسِہٖ تَبَرُّعًا مِنْ عِبَادَۃٍ اَوْصَدَقَۃٍ اَوْغَیْرَ ذٰلِکَ اس نے کوئی عبادت یا صدقہ وغیرہ اپنے اوپر فرض کر لیا.وَقِیْلَ النَّذْرُ مَا کَانَ وَعْدًا عَلٰی شَرْطٍ.اور کہا گیا ہے کہ نذر شرطی وعدہ کوبھی کہتے ہیں.مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ایسا کروںگا.(اقرب) تفسیر.اس آیت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جو خرچ بھی تم خرچ کرو اور جو نذر بھی تم نذر دو مگر یہ ترجمہ اردو محاورہ کے لحاظ سے درست نہیں.اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہو گا کہ ’’جو کچھ بھی تم خدا کے لئے خرچ کر ویا جو کچھ بھی تم نذر دو‘‘.کیونکہ اردو میں جو مضمون ’’کرو‘‘ یا ’’دو‘‘ کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے عربی زبان میں اس کے اسم سے فعل بنا کر لے آتے ہیں اور اس سے وہ مضمون ادا کرتے ہیں.ہاں عربی کی ترکیب سے یہ زائد معنے ضرور پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کو خرچ کیا جائے وہ خرچ کرنے کے قابل ہو.اور جو نذر دووہ نذر میں پیش کرنے کے قابل ہو.نذر کے متعلق حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا(مسلم کتاب النذر باب النھی عن النذر).ہاں اگر کوئی نذر مانی جائے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے.نذر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے اس لئے ناپسند فرمایا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ سے ایک قسم کا ٹھیکہ ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ٹھیکہ کرنا کوئی پسندیدہ امر نہیں.انسان کو چاہئے کہ وہ اس کی بجائے صدقہ و خیرات اور دعائوں سے کام لے.ہاں !اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوئی نذر بھی شکرانہ کے طور پر مان لے تو اس میں کوئی حرج نہیں.میں یہ استنباط حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ و السلام کے ایک عمل سے کرتا ہوں.آپ بعض دفعہ ان لوگوں کو جو آپ سے دعا کے لئے عرض کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کروںگا.آپ اپنے دل میں خدمتِ دین
Page 493
کے لئے کوئی رقم مقرر کر لیں جسے اس کام کے پورا ہونے پر آپ خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکرانہ کے طور پر اگر کوئی نذر مان لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں.بشرطیکہ اس نذر کے ساتھ ساتھ دعائوں اور گریہ و زاری اور صدقات و خیرات سے بھی کام لیا جائے.فَاِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُہٗ میں بتایا کہ تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو یا تم کوئی منت مانتے ہو اور اپنے اوپر واجب کر لیتے ہو اور پھر اس نذر کو پورا بھی کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے کیا کچھ دیا اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں کتنا اخلاص اور کتنا جذبۂ ایمان کام کر رہا تھا.پس وہ تمہارے اخلاص کے مطابق تمہیں اجر دے گا.اور تمہارا انفاق رائیگاں نہیں جائے گا.بلکہ وہ تمہیں بہت بڑی برکات سے حصہ دینے والا ثابت ہو گا.فَاِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُہٗ میں یہ اشارہ مخفی ہے کہ محض روپیہ خرچ کر دینا یا نذر کوپورا کر دینا کافی نہیں بلکہ دل کی نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کسی نے نام و نمود کے لئے خرچ کیا ہے یا محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور بنی نوع انسان کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر کام کر رہا ہے.وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ کسی کے زیادہ دوست ہوتے ہیں اور کسی کے کم مگر ظالم ایسا ہوتا ہے کہ جب اسے دنیوی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو جو لوگ اسے مدد دے سکتے ہیں وہ بھی نہیں دیتے اور اس سے الگ ہو جاتے ہیں.اور اگر روحانی نقطۂ نگاہ لو تو اصل مددگار خدا تعالیٰ اور اس کے ملائکہ ہیں یا صلحاء اور اولیاء ہیں.مگر ظالم کو ان میں سے کسی کی مدد میسر نہیں آتی اور وہ بے یارومددگار رہ کر اپنے جرم کی سزا پاتا ہے.اس جگہ ظالم سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے سے ہچکچاتے ہیں اور بخل کا شکار رہتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے مال خرچ کیا تو وہ مفلس اور کنگال ہو جائیں گے اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں.فرماتا ہے.یہ نقطۂ نگاہ دنیوی لحاظ سے بھی غلط ہے اور روحانی لحاظ سے بھی.دنیا میں جو دوسروں کے لئے روپیہ خرچ کرتا ہے.اور رفاہ عامہ کے کاموں میں حصہ لیتا ہے.ضرورت پڑنے پر اور لوگ بھی اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں.یا کم سے کم اس سے ہمدردی رکھتے اور اس کی اخلاقی مدد کرتے ہیں.مگر غرباء کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والے اور دوسروں کی تکالیف میں ہمدردی اور غمخواری نہ کرنے والے خوشحالی میں تو مست رہتے ہیں مگر جب اُن پر مصائب اور آفات آتی ہیں تو لوگ ان سے کسی قسم کی ہمدردی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے حالانکہ ہر انسان خواہ کتنا بڑا ہو مصیبت میں دوسروں کی ہمدردی اور محبت اور اعانت کا محتاج ہوتا ہے.اور اگر روحانی نقطہ ٔ نگاہ لو تو یہ تو واضح ہی ہے کہ جس شخص نے خدا کے لئے روپیہ خرچ نہ کیا یا قوم کے غرباء کی پرورش اور ان کی بہبودی کا خیال نہ رکھا اسے
Page 494
خدا اور اس کے ملائکہ کی نصرت اور اس کے پاک بندوں کی دعائیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ وہ ان تمام نعمتوں سے محروم رہے گا اور اپنے ہاتھوں اپنی تباہی مول لے گا.اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ١ۚ وَ اِنْ تُخْفُوْهَا وَ اگر تم علی الاعلان صدقے دو تو یہ (بھی )بہت اچھا (طریق )ہے.اور اگر تم وہ (یعنی صدقات )چھپا کر تُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ١ؕ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ غریبوں کو دو تو یہ تمہارے (نفس کے )لئے زیادہ اچھا ہے.اور وہ (یعنی اللہ اس کےسبب سے) تمہاری کئی بدیوں سَيِّاٰتِكُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ۰۰۲۷۲ کوتم سے دور کر دے گا.اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے.حلّ لُغات.یُکَفِّرْ عَنْکُمْ کَفَّرَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں سَتَرَہٗ اس پر پردہ ڈالا.اور کَفَّرَ اللّٰہُ لَہُ الذَّنْبَ کے معنے ہیں مَحَاہُ اس کا گناہ مٹا دیا ہے.اور کَفَّرَعَنْ یَمِیْنِہٖ کے معنے ہیں.اَعْطٰی مِنْھَا الْکَفَّارَۃَ قسم کا کفارہ دیا.( اقرب) پس یُکَفِّرُعَنْکُمْ کے معنے ہیں وہ تمہاری کمزوریوں پر پردہ ڈال دے گا یا تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا.تفسیر.اس آیت میں صدقات کے ظاہر طور پر خرچ کرنے کے متعلق تو فرمایا کہفَنِعِمَّا هِيَ.اور پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کے متعلق فرمایا خَیْرٌ لَّکُمْ.نِعِمَّا ھِیَ اصل میں نِعْمَ مَا ھِیَ ہے.(تفسیر الخازن) یہ طریق کلام مخصوص بالمدح کہلاتا ہے.اور اس سے مراد نِعْمَ الشَّیْءُ شَیْئًا ہوتا ہے.جیسے اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ بس کام ہے تو یہ ہے.لیکن اخفاء کے لئے خَیْرٌ لَّکُمْ کے الفاظ استعمال فرمائےکیونکہ اظہار کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے اور ان کو بھی صدقات کی تحریک ہوتی ہے جبکہ اخفاء کا اثر صرف انسانی قلب پر پڑتا ہے اور وہ کبر اور مَنْ اور اَذٰی سے محفوظ رہتا ہے.گویا نِعِمَّا ھِیَ میں وسعتِ دائرہ اور محدود نیکی کا ذکر کیا.اور خَیْرٌ لَّکُمْ میں محدود دائرہ اور اعلیٰ نیکی کا ذکر کیا.تُبْدُوْا الصَّدَقٰتِ میں قومی چندے اور تُخْفُوْھَا میں فردی خیرات مراد ہے.کیونکہ اوّل الذکر کا فائدہ ساری قوم کو اور ثانی الذکر کا فائدہ زیادہ تر اپنے نفس کو پہنچتا ہے.اسی لئے اس کے ساتھ لَکُمْ کا لفظ
Page 495
بڑھا دیا گیا ہے.لیکن ایک اور نقطہ نگاہ سے پہلے فقرہ میں زیادہ خصوصیت پائی جاتی ہے کیونکہ پہلے فقرہ میں یہ نہیں فرمایا کہ اظہارِصدقہ کس کے لئے اچھا ہے؟ مگر دوسرے فقرہ میں لَکُمْ کہہ کربتایا کہ تمہارے لئے بہتر ہے.اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم ظاہر طور صدقہ دو گے تو اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا کیونکہ جب لوگ کسی کو صدقہ دیتے دیکھیں گے تو کہیں گے آئو ہم بھی اس کی نقل کریں اور انہیں بھی تحریک ہو گی کہ وہ غرباء پروری میں حصہ لیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ہے کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِیَّتِہٖ (بخاری کتاب الجمعۃ باب الجمعۃ فی القرٰی و المدن) یعنی تم میں سے ہر ایک کی مثال ایک گڈریا کی سی ہے اور ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھیڑیں لگی ہوئی ہیں.جو اس کی نقل کرتی ہیں.پس اگر کوئی ظاہر طور پر صدقہ دے گا.تو اس کے بیٹے بھائی یا دوسرے رشتہ دار اسی طرح ملازم دوست اور آشنا وغیرہ بھی اس کی نقل میں صدقہ دیں گے اور یہ نیکی ترقی کرے گی.دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ آئندہ نسل کو فائدہ پہنچے گا اور بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت پڑ جائے گی کیونکہ جب وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں گے کہ وہ صدقہ دیتے ہیں.تو سمجھیں گے کہ یہ بھی اچھی بات ہے.اور اس طرح ان کی نیک تربیت ہو گی.تیسرا فائدہ یہ ہو گا کہ بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں شخص امداد کا مستحق ہے.جب وہ دوسروں کو ان کی امداد کرتے دیکھیں گے تو انہیں بھی ان کی غربت کا علم ہو جائے گا اور وہ بھی اپنے طور پر ان کی مدد کرنے لگ جائیں گے.پھر فرمایا کہ اگر تم پوشیدہ دو گے تو تمہارے اپنے نفس کی اصلاح کے لئے یہ طریق زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس سے ریا پیدا نہیں ہو گا جو ظاہر طور پر دینے سے پیدا ہو سکتا ہے بلکہ اس اخفاء کا ایک خاص انعام بھی بتایا کہ تم دوسروں کی کمزوری چھپائو گے.تو خدا تعالیٰ تم سے بھی یہی سلوک کرے گا.چنانچہ فرمایا.وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ وہ تمہاری بدیوں کو تم سے دور کر دے گا او رتم کو پاک بنادے گا.اس آیت میں مِنْ تبعیض کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور زائدہ بھی.اگر مِنْ تبعیضیہ لیا جائے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ تمہارے بعض گناہ تمہاری طرف سے مٹا دے گا.اس لئے یہاں یُکَفِّرُلَکُمْ نہیں فرمایا بلکہ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ فرمایا ہے کیونکہ انسانی گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انسان کے اور ایک خدا کے.خدا اپنے گناہ تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کے نہیں.کیونکہ اس میں ان کی معافی کی شرط ہوتی ہے.گویا بتایا کہ جب تم غریبوں کی کمزوریوں اور عیبوں کو چھپائو گے اور ایسا طریق اختیار کرو گے کہ لوگوں پر ان کی کمزوری ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری بعض بدیوں کو مٹا دے گا.یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو گناہ ہوں گے وہ انہیں معاف کر دے گا.
Page 496
دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ تمہاری بدیوں کے متعلق اپنے پاس سے کفارہ دے دےگا.یعنی وہ لوگ جن کے تم نے گناہ کئے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے صلہ دے کر کہے گا کہ یہ ہمارا بندہ ہے ہم تمہیں انعام دے دیتے ہیں تم اس کے گناہ معاف کر دو اس طرح وہ حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے گناہ بھی معاف کرا دے گا.کیونکہ جب نیکی ایک خاص حد تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف سے وکیل ہو کر بندہ سے اس کا گناہ معاف کرا دیتا او راس کو اپنے پاس سے بدلہ دےدیتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے.اس کے ایک یہ معنے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو خود تمہاری نظروں سے بھی چھپا دے گا.دراصل انسان کو خواہ کتنا ہی کہا جائے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا ہے پھر بھی یہ خلش اس کے دل میں باقی رہ جاتی ہے کہ میں نے گناہ کیا اور ایک شرمندگی اسے محسوس ہوتی ہے.اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو خود تمہاری نظروںسے چھپا دے گا یعنی خود تمہیں بھی اپنے گناہ بھلا دے گا اور تم اپنے حافظہ اور ذہن کے کسی گوشہ میں بھی ان کا کوئی نشان نہ دیکھو گے.سبحان اللہ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ کیا ہی مکمل فقرہ ہے.یہ ایسا اعلیٰ درجہ کا فقرہ ہے کہ کوئی اور فقرہ اس کی بجائے رکھا ہی نہیں جا سکتا.کیونکہ گناہ کے متعلق کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس میں آنہ گیا ہو.اخفش نے اس آیت میں من کو زائدہ قرار دیا ہے(املاء ما من بہ الرحمٰن) جوبغرض تاکید بھی ہو سکتا ہے.اس صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ تمہاری بدیاں بالکل مٹا دے گا.اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نے زکوٰۃ اور صدقات کو الگ الگ کیوں رکھا ہے.سو یادرکھنا چاہئے کہ زکوٰۃ بوجہ گورنمنٹ کی معرفت وصول ہونے کے ایک قسم کا ٹیکس معلوم ہوتی ہے.دوسرے زکوٰۃ کا دینا فرض ہے پس زکوٰۃ نہ دینا یا زائد دینا یا کم دینا انسان کے لئے ناممکن ہے.سو اللہ تعالیٰ نے ایک طریق تو زکوٰۃ کا رکھا تاکہ ہرمالدار کچھ نہ کچھ ضرور دے جس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو اور تاکہ غرباء کے لئے بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا طریق صدقات کا رکھا.اور صدقہ اس لئے مقرر کیا تا مخلص اور غیر مخلص کا فرق معلوم ہو.اور انسان کو اپنے ہاتھ سے دینے کی مشق ہو اور تا سِرًّا وَ عَلَانِیَۃً دینے کا اسے موقعہ ملے کہ سرّاً دینا محبت کو بڑھاتا اور گناہوں کو بخشواتا اور ان پر پردہ ڈالتا ہے.اور علانیۃً دینے سے دوسروں کو بھی صدقات کی تحریک ہوتی ہے.
Page 497
لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ١ؕ وَ انہیں راہ پر لانا تیرے ذمہ نہیں ہے.ہاں اللہ( تعالیٰ) جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے.اور جو اچھا مال بھی تم مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ۠١ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ( خدا کی راہ) میں خرچ کرو اور حقیقت یہ ہے کہ تم ایسا خرچ صرف اللہ کی توجہ چاہنے کے لئے ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ١ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ کیا کرتے ہو سو اس کا نفع بھی تمہاری (اپنی) جانوں ہی کو ہوگا.اور جو اچھا مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہیں پورا پورا وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ۰۰۲۷۳ (واپس کر )دیا جائے گا.اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا.تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ باتیں بیان فرمائی ہیں.اول رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے متعلق فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت دینا تیرے ذمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.ہدایت کے تین معنے ہوتے ہیں اوّل راستہ دکھانا دوم راستہ تک پہنچانا.سومآگے آگے چل کر منزل مقصود تک لئے جانا (اقرب).پہلی قسم کی ہدایت تو ایسی ہے جس میں بندہ بھی شریک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بھی دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے.لیکن آخری دو ہدایتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں.یعنی صحیح راستہ تک پہنچانا.اور پھر اس راستہ پر قائم رکھتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچانا کسی بندہ کے اختیار میں نہیں.یہاں چونکہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہدایت پا چکے ہیں اس لئے فرمایا کہ ان کو ہدایت پرقائم رکھنا اور انہیں منزل مقصود تک پہنچانا یہ تیرا کام نہیں.اللہ تعالیٰ جسے قائم رکھنے کے قابل سمجھتا ہے اسے قائم رکھتا ہے اور جسے ناقابل سمجھتا ہے اسے گرا دیتا ہے.دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو کچھ بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہاری جانوں کو ہی ہو گا.یہاں خَیْـرٌ کا لفظ اس لئے رکھا کہ خیر کے معنے مال کے بھی ہوتے ہیں اور اچھے مال کے بھی.یعنی ایسے مال کے جو اچھے ذرائع سے کمایا گیا ہو یا مقدار میں زیادہ ہو.پس خیر کا لفظ استعمال فرماکر اس طرف توجہ دلائی کہ تم صرف اپنا مال ہی خرچ نہ کرو بلکہ یہ بھی دیکھتے رہو کہ وہ مال اچھے ذرائع سے کمایا ہوا ہو اور پھر قربانی بھی اپنی حیثیت کے
Page 498
مطابق ہو.یہ نہ ہو کہ مثلاً تنخواہ تو چار سو روپیہ ہے اور پانچ روپے چندہ دے کر سمجھ لیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا حق ادا ہو گیا ہے.پھر مال خرچ کرنے پر سوال ہوتا تھا کہ ہم نے اپنا مال تو لوگوں کو دے دیا مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہو گا.تمہارا یہ مال خرچ کرنا ایسا ہی ہے جیسے زمیندار کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس سے ہزاروں دانے بن جاتے ہیں.وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے دانے کیوں ضائع کروں؟ اسی طرح تم بھی یہ مت خیال کرو کہ اگر تم مال خرچ کرو گے تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا کیونکہ اس کے نتیجہ میں قوم ترقی کرے گی اور قوم کی ترقی سے فرد بھی ترقی کرتا ہے.دراصل ایسا خیال قلت ِ تدبر کا نتیجہ ہوتا ہے.ورنہ یوروپین قومیں جنہوں نے اس نکتہ کو خوب سمجھا ہے وہاں دولتمند گو اس بات میں بدنام ہیں کہ وہ ہر وقت عیش و عشرت میں مبتلا رہتے ہیں لیکن وہ پھر بھی غرباء کو ابھارنے اور قوم کو ترقی دینے کے لئے اپنے اموال کا ایک بڑا حصہ ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں.اور اس طرح عیسائیت کی تقویت کا موجب بنتے ہیں.وَ مَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ فرماتا ہے کہ بے شک غرباء کے لئے اپنے اموال خرچ کرنا قومی نقطہ ٔ نگاہ سے بھی مفید ہے لیکن صرف اس فائدہ کو ہی اپنا مقصد و مدّعا نہ بنا لینا.ایک مسلمان سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ خرچ کرے گا خالصۃً لِّٰلہ اور ابْتِغَآءَلِوَجْهِ اللّٰهِ کرےگا.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف کی ہے اور نفی کے طور پر یہ فقرہ بیان کیا ہے.جس کے معنے یہ ہیں کہ ہم مومنوں سے اس کے سوا اور کسی چیز کی توقع ہی نہیں کر سکتے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضاکے لئے خرچ کریں گے.یہ طریق کلام نہی کی نسبت زیادہ مؤثر ہوتا ہے جیسے اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میری واپسی تک آپ یہیںتشریف رکھیں گے.تو یہ فقرہ بہ نسبت اس بات کے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ یہیں بیٹھیں.اور میرے آنے تک کہیں نہ جائیں کیونکہ اس طرح خود اس کے دل میں کام کرنے کی تحریک پیدا کی جاتی ہے.پھر وَ مَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ کہہ کر اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ بے شک مومنوں کے چندوں سے دنیوی ترقیات بھی حاصل ہوتی ہیں او ردین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے مگر اعلیٰ درجہ کے مومن اس سے بالا ہوتے ہیں.انہیں نہ دنیا کی ترقی مطلوب ہوتی ہے اور نہ جنت کے انعامات ان کا اصل مقصود ہوتے ہیں بلکہ ان کی نیکیوں کا حقیقی محرک صرف یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور وہ انہیں محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھے.چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا.اللہ تعالیٰ
Page 499
نے اس امر کو اِبْتِغَآءَ لِوَجْهِ اللّٰهِ کے بعد بیان کیا ہے.حالانکہ جہاں یہ بتایا تھا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہاری جانوں کو پہنچے گا اسی جگہ یہ بات بھی بیان کی جا سکتی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں رکھا.اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک مزید بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے تو پورا پورا بدلہ مل جاتا ہے مگر جو شخص دنیا کی خاطر دیتا ہے اسے دنیا میں تو لوگوں کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے مگر آخرت میں اسے کوئی انعام نہیں ملتا.آخر میں وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ کہہ کر ایک اور ظلم کی بھی نفی کی گئی ہے جس کا گذشتہ آیات کے تسلسل میں جنگ کے ساتھ تعلق ہے جو قوم جنگ کے موقعہ پر اپنا مال خرچ نہ کرے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور دوسری قوم غالب آکر اسے اپنے مظالم کا تختہ مشق بنا لیتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنا مال خرچ کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے اور کوئی دوسری قوم تمہیںمغلوب کر کے تم پر ظلم نہیں کر سکے گی.لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ (یہ مذکورہ بالا صدقات )ان محتاجوں کے لئے ہیںجو اللہ کی راہ میں (دوسرے کاموں سے) روکے گئے ہیں.وہ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ١ٞيَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ ملک میں (آزادی سے )آ جا نہیں سکتے (ایک) بے خبر(شخص ان کے) سوال سے بچنے کے سبب سے انہیں غنی خیال التَّعَفُّفِ١ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰىهُمْ١ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ کرتاہے.تم ان کی ہیئت سے پہچان سکتے ہو.وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے.اور تم جو اچھا مال بھی اِلْحَافًا١ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌؒ۰۰۲۷۴ (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو اللہ اس سے خوب واقف ہے.حلّ لُغات.ضَرْبًا فِی الْاَرْضِ ضَرَبَ فِی الْاَرْضِ کے معنے ہیں خَرَجَ تَاجِرًا اَوْ غَازِیًا وہ تجارت کرنے یا جنگ کرنے کے لئے نکل گیا.اور ضَرَبَ کے معنے اَسْرَعَ اور ذَھَبَ کے بھی ہیں یعنی اس نے جلدی کی اور
Page 500
چلا گیا.(اقرب) اَلتَّعَفُّفُ عَفَّ الرَّجُلُ کے معنے ہیں کَفَّ عَمَّا لَایَحِلُّ وَ لَایَجْمُلُ قَوْلًا اَوْ فِعْلًا وَامْتَنَعَ.اس چیز سے جو جائز او راچھی نہیںقولی یا فعلی طور پر رک گیا.(اقرب) اس جگہ مِنْ کے معنے سبب کے ہیں.جیسا کہ آتا ہے مِمَّاخَطِیْئٰتِھِمْ اُغْرِقُوْا (نوح:۲۶) وہ اپنے گناہوں کے سبب سے غرق کر دیئے گئے.سِیْمَا کے معنے ہیں (۱) ہیئت (۲) علامت.(اقرب) اِلْحَافًا اَلْحَفَ السَّائِلُ کے معنے ہیں اَلَـحَّ.سائل نے اصرار سے کام لیا.اور اَلْحَفَ فُـلَانًا الثَّوْبَ کے معنے ہیں اَلْبَسَہٗ اِیَّاہُ اسے لباس پہنا دیا گیا.پس اِلْحَافٌ کے معنے ہوئے پہنانا یعنی سوال پہنا دینا مراد اِس سے یہ ہے کہ کسی کا پیچھا نہ چھوڑنا اور سوال کرتے چلے جانا.(اقرب) تفسیر.لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ یہ ایک محذوف کی خبر ہے جو ھِیَ کا لفظ ہے.اور اس کے معنے یہ ہیں کہ یہ صدقہ کا حکم جو تمہیں دیا گیا ہے یہ فقراء کے لئے ہے.یا اس جگہ ایک فعل محذوف ہے.جو اِجْعَلُوْھَا ہے.یعنی اس صدقہ کو ان فقراء کے لئے مخصوص کردو جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں روکے گئے ہیں.یہاں اُحْصِرُوْا تو فرما دیا مگر یہ نہیں بتایا کہ کون روکتا ہے یا وہ کس وجہ سے رکتے ہیں.ا س کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عام رکھنا چاہتا ہے کیونکہ روکے جانے کی کئی وجوہ ہو سکتی تھیں.بہرحال اس سے یہ امر یقینی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ نکمے اور سست نہیں ہوتے بلکہ کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں.آگے وہ مجبوری بیان نہیں کی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دشمن روکنے والا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدمت دین کے کاموں میں رات دن مصروف رہنے کی وجہ سے دنیا کمانے کے دروازے ان پر بند ہوں.جیسے صحابہؓمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبۂ عشق اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے کی تمنّا اور دین اسلام سیکھنے کی تڑپ اتنا کام کررہی تھی کہ انہیں کسی اور بات کی طرف توجہ ہی نہیں تھی.اس کی مثال حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے.جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف تین سال قبل ایمان لائے تھے.وہ خودبیان کرتے ہیں کہ میں چونکہ بعد میں ایمان لایا تھا.اس لئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپؐ کے دروازہ کو نہیں چھوڑوں گا.چنانچہ وہ اپناتمام وقت مسجد میں گذارتے اور قضائے حاجات کے بعد پھر وہیں آکر بیٹھ جاتے.ان کو کہیں باہر جانا پسند ہی نہیں تھا تا ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کوئی بات فرمائیں اور وہ اسے سن نہ سکیں.یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تین سال کے عرصہ کی صحبت پانے کے باوجود اس قدر حدیثیں بیان کی ہیں کہ ان
Page 501
سے بہت زیادہ عرصہ صحبت پانے والوں نے اتنی حدیثیں بیان نہیں کیں.ان کے بھائی نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ یارسول اللہ ابوہریرہ سارا دن بیکار پڑا رہتا ہے.آپ اسے ہدایت فرمائیں کہ وہ کوئی کا م بھی کیا کرے.آپ نے فرمایا.کبھی خدا تعالیٰ دوسروں کی وجہ سے بھی رزق دے دیا کرتا ہے.تمہیں کیا معلوم کہ اسی کی وجہ سے خدا تعالیٰ تم کو رزق دے رہا ہو؟پس ایسے واقفین زندگی جنہوں نے اپنے تمام اوقات خدا اور اس کے رسول کے لئے وقف کر رکھے ہوں اور وہ کوئی تجارت وغیرہ نہ کر سکتے ہوں وہ بھی اُحْصِرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ میں ہی شامل ہیں.پھر ایک رُکنا وہ بھی ہے جس کا فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (التوبۃ: ۱۲۲)میں ذکر آتا ہے.یعنی کیوں نہ ہوا کہ ہر قوم اور جماعت کے کچھ لوگ مرکز میں دین سیکھنے کے لئے آتے اور اپنی قوم کو واپس لوٹ کر بے دینی سے ہوشیار کرتے تاکہ وہ گمراہی سے ڈریں.جیسا کہ اس زمانہ میں مختلف ممالک سے لوگ دین سیکھنے کے لئے احمدیت کے مرکز میں آتے اور کئی کئی سال تک تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر واپس جا کر اپنے ملک اور قوم کے لئے ہدایت اور راہنمائی کا موجب بنتے ہیں.پس ایک رُکنا دین حاصل کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے.وہ اپنے نفس کے آرام کے لئے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اس کے دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے روکے جاتے ہیں.وہ زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے یعنی ہر وقت دین کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں.اور انہیں دینی امور میں اتنا شغف ہوتا ہے کہ معاش کے حصول کے لئے کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کر سکتے لیکن مال کی کمی کے باوجود وہ اپنے نفس کو سوال کی دناء ت سے بچاتے اور خاموش رہتے ہیں.اور اس وجہ سے وہ لوگ جو غور کرنے کے عادی نہیں انہیں خوشحال سمجھ لیتے ہیں.ایسے لوگوں کے متعلق تمہارا فرض ہے کہ تم خود ان کی ضروریات کا خیال رکھو اور ان کے لئے اپنے اموال کا ایک حصہ خرچ کرو.اس آیت کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے لوگوں نے کسبِ معاش سے روک دیا ہے جیسے کئی احمدی ہیں جن کو محض قبول احمدیت کی وجہ سے ملازمتوں وغیرہ سے الگ ہونا پڑ ایا کسبِ معاش کے ذرائع ان پر بند کئے گئے.يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ایسے لوگ چونکہ دستِ سوال دراز نہیں کرتے اس لئے جاہل لوگ انہیں تعفف کی وجہ سے مالی امداد سے بالا سمجھتے ہیں حالانکہ عزّت نفس نے ان کے لبوں پر مہر خاموشی لگائی ہوئی ہوتی ہے ورنہ وہ بعض محتاج دکھائی دینے والوں سے بھی زیادہ قابلِ امداد ہوتے ہیں اور ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی
Page 502
مناسب امداد کی جائے اور ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے تاکہ وہ دینی خدمات کو خوش اسلوبی سے سرانجام دے سکیں.میں نے دیکھا ہے عام طور پر لوگوں کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے کسی نے مانگا ہے کہ ہم دیں.حالانکہ یہ آیت بتاتی ہے کہ مومن کا یہ ذاتی فرض ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کر حالات کا صحیح جائزہ لے اور دیکھتا رہے کہ کون حاجتمند ہے اور کون ہے جسے عزتِ نفس نے سوال کرنے سے روک رکھا ہے.تَعْرِفُھُمْ بِسِیْمٰھُمْ میں بتایا کہ تو ان کی علامت یا شکل ہی سے ان کو پہچان لیتا ہے.سِیْمَاکے معنے اگر شکل اور حالت کے لئے جائیں تو مطلب یہ ہو گا کہ تو ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ وہ مالی پریشانی کا شکار ہیں اور اگر علامت کے معنے لئے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ تو ان کا دریدہ لباس اور ان کی پھٹی پرانی جوتی.ان کی بوسیدہ پگڑی اور ان کی سادہ طرز رہائش پر نظر ڈال کر پہچان لیتا ہے کہ یہ لوگ قابلِ امداد ہیں.اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے مومنوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمارا رسول تو ایسے لوگوں کو پہچان لیتا ہے پھر تم کیوں نہیں پہچانتے اور کیوں اپنی آنکھیں کھول کر نہیں رکھتے.اس بارہ میں احادیث میں حضرت ابوہریرہؓ ہی کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے.ایک دن وہ سخت بھوکے تھے.حضرت ابوبکرؓ پاس سے گذرے تو انہوں نے ان سے ایک آیت کا مطلب پوچھا.وہ بتا کر چلے گئے.حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں.میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا میں ان سے کم معنے جانتا ہوں کہ وہ معنے بتانے لگ گئے؟ میرا تو یہ مطلب تھا کہ وہ شکل دیکھ کر پہچان لیں اور مجھے کچھ کھانے کو دیں.پھر حضرت عمرؓ پاس سے گزرے انہوں نے آپ سے بھی ایک آیت کا مطلب پوچھا.وہ بھی معنے بتا کر چلے گئے.حضرت ابوہریرہؓ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کیا ابوہریرہ ؓ ان سے کم معنے جانتا ہے کہ انہوں نے آیت کے معنے بتائے اور چلے گئے.اتنے میں مسجد کی ایک طرف سے کھڑکی کھلی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا.ابوہریرہ! معلوم ہوتا ہے.تم بھوکے ہو.پھر آپ نے فرمایا.اگر مسجد میں کچھ اَور لوگ بھی بیٹھے ہوں تو ان کو بھی بلا لائو.اس وقت مسجد میں سات آدمی تھے.حضرت ابوہریرہؓ ان کو بلا لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا ایک پیالہ دے کر فرمایا کہ پہلے ان کو پلائو.حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں.میرے دل میں خیال آیا کہ بھوک تو مجھے لگی ہوئی ہے اگر انہوں نے دودھ پی لیا تو میرے لئے کیا بچے گا.لیکن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے حکم کے مطابق ان کو باری باری دودھ پلایا اور سب نے پی لیا مگر پھر بھی وہ پیالہ اسی طرح بھرا رہا.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابوہریرہ! اب تم پیو.آخر میں نے پیا اور خوب پیا.جب میں سیر ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پیو.میں نے پھر پیا.آپ نے فرمایا.
Page 503
پھر پیو.میں نے پھر پیا.آپ نے فرمایا پھر پیو.آخر میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! اب تو میرے ناخنوں تک دودھ کی تراوت پہنچ گئی ہے.اس پر آپ نے وہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے لیا اور خود پی لیا(بخاری کتاب الرقاق باب کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم).یہ تَعْرِفُھُمْ بِسِیْمٰھُمْ کی صداقت کا کتنا زبردست ثبوت ہے.غرض اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ ہمارا رسول ایسے محتاجوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیتا ہے.پس اے مسلمانو! تم بھی ان کو پہچاننے کی کوشش کیا کرو.لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا کے یہ معنے نہیں کہ وہ سوال تو کرتے ہیں مگر لوگوں سے چمٹ کر نہیں صرف نرمی سے مانگ لیتے ہیں.بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ وہ لوگوں سے سوال ہی نہیں کرتے.گویا اِلحاف سوال کو مقید کرنے کے لئے نہیں بلکہ سوال کی شناعت بیان کرنے کے لئے ہے.یعنی وہ الحاف نہیں کر سکتے.کیونکہ الحاف چاہتا ہے کہ انسان دائماً مسئول عنہ کے ساتھ لگا رہے اور وہ خدا کے لئے وقف ہو چکے ہیں.پس وہ اپنی غربت چھپانے کے لئے امراء کا سایہ بننے سے بھی گریز کرتے ہیں اور اس طرح دوسرے لوگوں سے جو سوال مجسم بن کر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے بھی محروم رہتے ہیں.گویا یہ الفاظ بطور تفسیر ہیں نہ کہ بطور قید.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے بھی یہی معنے ثابت ہیں.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں.لَیْسَ الْمِسْکِیْنُ الَّذِیْ تَرُدُّہُ التَّمْرَۃُ اَوِالتَّمْرَتَانِ وَ لَا اللُّقْمَۃُ وَ لَا اللُّقْمَتَانِ اِنَّمَا الْمِسْکِیْنُ الَّذِیْ یَتَعَفَّفُ وَ اقْرَءُ وْ ا اِنْ شِئْتُمْ یَعْنِیْ قَوْلَہٗ لَایَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا (بخاری کتاب التفسیرباب قول اللہ عزّوجلّ لا یسئلون الناس الحافًا) یعنی مسکین وہ نہیں جسے ایک یا دو کھجوریں یا ایک لقمہ یا دو لقمے دے دیں بلکہ مسکین وہ ہے جو سوال ہی نہیں کرتا.یہ اِلحاف کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تفسیر بیان فرمائی ہے.اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے.لَیْسَ الْمِسْکِیْنُ الَّذِیْ یَطُوْفُ عَلَی النَّاسِ تَرُدُّہُ اللُّقْمَۃُ وَ اللُّقْمَتَانِ وَ التَّمْرَۃُ وَالتَّمْرَتَانِ وَ لٰـکِنَّ الْمِسْکِیْنَ الَّذِیْ لَایَجِدُ غِنًی یُغْنِیْہِ وَلَایُفْطَنُ بِہٖ فَیُتَصَدَّقَ عَلَیْہِ وَلَایَقُوْمُ فَیَسْئَلُ النَّاسَ.(بخاری کتاب الزکوٰۃ باب قول اللہ عزّوجل لَایَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا)یعنی مسکین وہ نہیں جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے اور اسے ایک دو لقمے یا ایک دو کھجوریں مل جاتی ہیں بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہو اور نہ لوگوں کو اس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اسے صدقہ ہی دے دیں اور نہ ہی وہ لوگوں سے سوال کر کے اپنی حاجت پوری کرے.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسکین دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک وہ جو لوگوں سے سوال کرتے پھرتے ہیں اور انہیں دوسروں سے مانگنے کی عادت ہو جاتی ہے.دوسرے وہ جو لوگوں سے
Page 504
مانگتے نہیں بلکہ کام کر کے روزی کماتے ہیں لیکن ان کی آمد اس قدر کم ہوتی ہے کہ وہ بھی قابل امداد ہوتے ہیں.بہرحال احادیث میں سوال کرنے سے سخت روکا گیاہے اور سوائے تین آدمیوں کے اور کسی کے لئے سوال کرنا جائز نہیں سمجھا گیا.چنانچہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اِنَّ الْمَسْئَلَۃَ لَاتَصْلِحُ اِلَّا لِثَـلَاثَۃٍ لِذِیْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ اَوْ لِذِیْ غَرْمٍ مُفْظِعٍ اَوْ لِذِیْ دَمٍ مُوْجِعٍ (مشکوٰۃ المصابیح کتاب الزکٰوۃ من لا تحلّ لہ مسئلۃ) یعنی تین آدمیوں کے سوا اور کسی کے لئے سوال کرنا جائز نہیں.اول اس کے لئے جس کو کھانے کے لئے کوئی چیز نہ ملتی ہو.یعنی ایسی حالت ہو گئی ہو کہ اور کسی ذریعہ سے اس کو کھانا ملنا ناممکن ہو.دوم جس پر بِلا اس کے کسی قصور کے چٹّی پڑ گئی ہو اور اسے وہ ادا نہ کر سکتا ہو.سوم.کوئی قتل ہو گیا ہو اور اس کی دیت ادا کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو.ایسے موقعہ پر اس کے لئے سوال کرنا جائز ہے.مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے معنے یہ ہوں کہ ان لوگوں کے لئے دوسروں کو سوال کرنا جائز ہے نہ کہ خود اس کو.اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ دو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالی بن کر آئے.آپؐ نے ان کو سرتا پا دیکھا اور فرمایا.اِنْ شِئْتَـمَا اَعْطَیْتُکَمَا مِنْھَا وَلَاحَظَّ فِیْھَا لِغَنِیٍّ وَلَالِقَوِیٍّ مُکْتَسِبٍ (مسند احمد بن حنبل جلد ۵ صفحہ ۳۶۲) یعنی اگر تم چاہو تو میں تم کو مال دے دیتا ہوں.مگر صدقہ کے مال میں صدقہ دینے والے آسودہ حال اور کمانے والے کا کوئی حق نہیں.اسی طرح آپ نے ایک اور موقعہ پر فرمایا کہ مَنْ سَأَلَ وَ عِنْدَہٗ مَا یُغْنِیْہِ فَاِنَّمَا یَسْتَکْثِرُ مِنْ نَارِجَھَنَّمَ یعنی جو شخص دوسروں سے سوال کرے اور اس کے پاس اتنی چیز موجود ہو جو اس کے کام آسکے تو وہ جہنم کی آگ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے.صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وَ مَا یُغْنِیْہِ کفایت کرنے والی چیز سے کیا مراد ہے؟ آپؐ نے فرمایا مَایُغْدِیْہِ اَوْ یُعْشِیْہِ ایسی چیز جو اس کے صبح یا شام کے کھانے میں کام آسکے.(مسند احمد بن حنبل جلد ۴ صفحہ ۱۸۱)غرض لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا میں بتایا کہ وہ لوگ دوسروں سے سوال ہی نہیں کرتے.کیونکہ خود سوال کرنا ہی اپنی ذات میں اِلحاف ہے.اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ سِرًّا وَّ جو لوگ اپنے مال رات اور دن پوشیدہ (بھی) اور ظاہر (بھی )(اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے رہتےہیں عَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ١ۚ وَ لَا خَوْفٌ ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا اجر (محفوظ )ہے.اور نہ (تو )انہیں کوئی خوف ہوگا
Page 505
عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَؔ۰۰۲۷۵ اور نہ وہ غمگین ہوں گے.تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے متعلق بعض اور امور بیان کئے ہیں.فرماتا ہے.ہمارے مومن بندے صدقہ کے لئے کسی خاص وقت یا خاص دن کو مخصوص نہیں کرتے بلکہ وہ رات کے وقت بھی صدقہ کرتے ہیں اور دن کے وقت بھی صدقہ کرتے ہیں.او رمخفی طور پر بھی صدقہ کرتے ہیں اور ظاہرطور پر بھی صدقہ کرتے ہیں.یہ لَیل اور نَہَار اور سِرًّا وَ عَلَانِیَۃً کا ذکر اس لئے فرمایا کہ شریعت اسلامی کے نزدیک مومن پر کوئی وقت ایسا نہیں آنا چاہیے جبکہ وہ نیکیوں میں حصہ نہ لے رہا ہو.چنانچہ نمازوں کی دن اور رات میں تقسیم اور روزوں اور حج کا قمری مہینہ میں رکھنا.یہ سب اسی غرض کے لئے ہے.پس دن اور رات میں سرا ًاو رعَلَانیۃً صدقہ دینے کا ذکر کر کے بتایا کہ ہمارے مومن بندے صدقہ بھی مختلف اوقات میں دیتے ہیں تاکہ کوئی وقت صدقہ سے خالی نہ رہے اور قمری مہینوں کے لحاظ سے ان کی یہ نیکی سارے سال میں چکر کھاتی رہے اور اس کا کوئی حصہ بھی اس سے خالی نہ رہے.اس جگہ اللہ تعالیٰ نے لیل کا ذکر پہلے کیا ہے اور نہار کا بعد میں اور اسی ترتیب سے سِرًّا کو پہلے رکھا ہے اور علانیۃً کو پیچھے یا یوں کہنا چاہیے کہ لیل کے مقابل میں سِرًّا رکھا ہے اور نہار کے مقابلہ میں علانیۃً.اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مومنوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بعض دفعہ رات کو پوشیدہ طور پر صدقہ دیتے ہیں اور اس طرح دیتے ہیں کہ لینے والے کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ کس نے دیاہے تاکہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو اور ان کے اپنے قلب میں بھی تکبر اور ریا کا جذبہ پیدا نہ ہو.پھر وہ دن کو بھی صدقہ دیتے ہیں اور ظاہر طور پر دیتے ہیں تاکہ اسے دیکھ کر دوسروں کو بھی غرباء کی امداد کی تحریک ہو اور قوم ترقی کرے.ورنہ اپنی ذات کے لئے انہیں کسی شہرت کی تمنّا نہیں ہوتی.غرض لیل کی سِرًّا میں تفسیرکی گئی ہے اور نھار کی علانیۃً میں اور بتایا گیا ہے کہ ہمارے مومن بندے وقتوں کا بھی لحاظ رکھتے ہیں.اور حالتوں کا بھی لحاظ رکھتے ہیں.اسی طرح لیل و نھار سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ دکھ اورسکھ دونوں حالتوں میں وہ صدقہ دیتے ہیں.درحقیقت اگر غور سے کام لیا جائے تو اسلامی شریعت میں خدا تعالیٰ نے دو قسم کے صدقات رکھے ہیں.اول زکوٰۃ جو حکومت وصول کرتی ہے.یہ نظام اس لئے قائم کیا گیا ہے کہ غرباء کے لئے امداد کی ایک یقینی صورت پیدا ہو جائے.دومؔ صدقہ تاکہ اس کے ذریعہ مخلص اور غیرمخلص کا پتہ چلتا رہے جو شخص مخلص ہو گا وہ تو اپنے طور پر بھی صدقہ دے گا.لیکن زکوٰۃ چونکہ گورنمنٹ کی معرفت وصول کی جاتی
Page 506
ہے اس لئے وہ لوگوں کو ٹیکس کی طرح لازماً ادا کرنی پڑتی ہے اور اس میں مخلص اور غیرمخلص سب کو شامل ہونا پڑتا ہے پس اسلام نے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ بھی رکھ دیا تاکہ لوگوں کو خود بھی اس کا احساس رہے اور ان میں غرباء پروری کا جذبہ ترقی کرے.پھر زکوٰۃ کے قیام کی ایک غرض دوسروں کے جذبات کا احترام بھی ہے.کیونکہ زکوٰۃ کا روپیہ حکومت دیتی ہے اس لئےلینے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کس نے دیا ہے لیکن دوسری طرف صدقہ آپس کے تعلقات کو بھی خوشگوار بنانے کے لئے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے.غرض کچھ صدقہ غرباء اور فقراء کے لئے حتمی اور قطعی طور پر مقرر کر دیا اور باقی صدقات مخلصین کے امتیاز اور ان کے مدارج میں ترقی کے لئے رکھ دیئے.دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جب تک کھیت میں بیج نہ بویا جائے اس وقت تک فصل نہیں ہوتی.اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا.کہ پہلے تم اپنے پاس سے کچھ خرچ کرو پھر میں تمہیں دوں گا.بے شک خدا تعالیٰ بغیر بیج کے بھی پیدا کر سکتا ہے لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے ہی یہ قانون بنا دیا ہے کہ بغیر بیج کے ہم کچھ پیدا نہیں کریں گے اس لئے فرمایا کہ پہلے تم بیج ڈالو.پھر دیکھو گے کہ ہم اس بیج کو کس طرح بڑھاتے ہیں؟ لَاخَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَاھُمْ یَحْزَنُوْنَ میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا میں بیج بونے والا کبھی ثمرات سے محروم بھی رہتا ہے.مثلاً فصل کو آگ لگ جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے اور اس طرح اس پر خوف و حزن طاری ہو جاتا ہے.مگر فرمایا ہمارے ہاں ایسا نہ ہو گا.پھر دنیا میں تو ایک دانہ کے عوض سات سودانے ملتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اجر دیتا ہے اور وہ غیرمقطوع انعامات سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے.اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ (بالکل) اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ١ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس پر شیطان( یعنی مرض جنون )کا سخت حملہ ہو.یہ (حالت) اس وجہ سے ہے کہ وہ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا١ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ کہتے رہتے ہیں کہ( خرید و )فروخت (بھی تو) بالکل سود (ہی )کی طرح ہے.حالانکہ اللہ نے (خرید و) فروخت کو جائز
Page 507
حَرَّمَ الرِّبٰوا١ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے.سو( یاد رکھو کہ) جس( شخص) کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت مَا سَلَفَ١ؕ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ١ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ (کی بات) آئے اور وہ( اسے سن کر خلاف ورزی سے )باز آجائے تو جو (لین دین) وہ پہلے کر چکا ہے اس کا نفع اسی النَّارِ١ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۰۰۲۷۶ کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے.اور جو لوگ پھر (وہی کام) کریں وہ( ضرور) آگ (میں پڑنے ) والے ہیں.وہ اس میں پڑے رہیں گے.حلّ لُغات.تَـخَبَّطَہٗ کے معنے ہیں ضَرَبَہٗ شَدِیْدًا.اسے سخت مارا اور تَخَبَّطَہُ الشَّیْطٰنُ کے معنے ہیں مَسَّہٗ بِاَذًی.شیطان نے اسے سخت تکلیف پہنچائی.(اقرب) اَلْمَسُّ کے معنے ہیں اَلْجُنُوْنُ پاگل پن لِاَنَّہٗ عِنْدَ الْعَرَبِ یَعْرِضُ مِنْ مَسِّ الْجِنِّ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب کے نزدیک یہ عارضہ جنّات کے چُھونے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سُود خوار لوگوں اورسُود خوار قوموں کی حالت بیان کرتے ہوئے ان مضرات کا ذکر فرمایا ہے جوسُود کے ساتھ وابستہ ہیں اور جن کے نتیجہ میں نہ صرف امراء اور غرباء کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو جاتی ہے بلکہ دنیا کا امن بھی برباد ہو جاتا ہے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ ربوٰاکے لفظ میں ہر قسم کاسُود شامل ہے.اس میں بنکوں کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی.بلکہ خواہ بنک سے سود لیا جائے یا ڈاکخانہ سے یا کواپریٹو سوسائٹیز سے یا کسی فرد سے ہر صورت میں وہ ناجائز اور حرام ہے.مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے یوروپین اقوام سے ڈر کرسُود کی عجیب وغریب تعریفیں کرنی شروع کر دی ہیں.چنانچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کا سُود لینے کی تو ممانعت ہے کہ سو روپیہ دے کر دو سو لیا جائے لیکن معمولی سود لینے کی ممانعت نہیں کیونکہ یہ سُود نہیں بلکہ منافع ہے.ان لوگوں کی مثال بالکل اس کشمیری کی سی ہے جس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہارا کوئی لڑکا بھی ہے؟ اس نے کہا.کوئی نہیں.لیکن جب وہ اُٹھا تو
Page 508
چار لڑکے اس کے لمبے کرتہ کے نیچے سے نکل آئے.پوچھنے والے نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ میرا کوئی بچہ نہیں.یہ چار کس کے بچے ہیں.اس نے کہا.چار بچے بھی کوئی بچے ہوتے ہیں.یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ پانچ یا سات فیصدی سُودبھی کوئی سود ہے.سُود تو وہ ہے جو سو فیصدی ہو.بعض دوسروں نے یہ فتویٰ دے کر کہ غیرمسلموں سے سُود لینا جائز ہے اس کے جواز کی ایک اور راہ نکال لی ہے.پھر بعض نے یہ فتویٰ دے دیا کہ غیرمذاہب کی حکومتوں کے ماتحت جو مسلمان بستے ہیں ان سے بھی سُود لینا جائز ہے.آخر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ سُود وہ ہوتا ہے جو بہت بڑی رقم کی صورت میں لیا جائے اور پھر اس رقم کو معیّن نہیں کیا گیا کہ کتنی ہو؟ گویا کسی کے لئے بھی روک باقی نہ رہی اور سب کے لئے سود لینا جائز ہو گیا حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے سُود کو ایسی لعنت قرار دیا ہے کہ آپؐ نے ایک دفعہ فرمایا.سُود لینے والا اور دینے والا اور اس پر گواہی ڈالنے والا سب کے سب جہنم میں جائیں گے.(ترمذی کتاب البیوع باب ما جاء فی اکل الربا) درحقیقت سُود سے روکنا اسلام کے اعلیٰ ترین احکام میں سے ہے.اسلام یہ نہیں چاہتا کہ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت جمع ہو جائے اور باقی لوگ بھوکے مرتے رہیں بلکہ چاہتا ہے کہ سب کو ترقی کی دوڑ میں حصہ لینے کا یکساں موقع ملے اور تمدن اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہو اور اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر قسم کے سُودی کاروبار کو بند کیا جائے.کیونکہ سُود کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ امراء اس ذریعہ سے روپیہ حاصل کرکے ہر قسم کی تجارت اور صنعت و حرفت اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں.پس سُود ہی ہے جس نے اس زمانہ میں چند ہاتھوں میں دولت جمع کر دی ہے اور امراء اور غرباء میں ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی ہے.دراصل اگر غور سے کام لیا جائے تو سُود دو قسم کا ہوتا ہے.ایک وہ جو مال دار آدمی اپنا مال بڑھانے کے لئے دوسرے مال داروں سے رقم لے کر ان کو ادا کرتا ہے.جیسے تاجرپیشہ لوگو ں یا بینکوں کا دستور ہے.اور ایک وہ سُود ہے جو غریب آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کسی صاحبِ استطاعت سے قرض لے کر اسے ادا کرتا ہے.اسلام نے ان دونوں سُودوں سے منع کیا ہے.اس سُود سے بھی روکا ہے جو تجارت یا جائیداد کو فروغ دینے کے لئے مال داروں سے روپیہ لے کر انہیں ادا کیا جاتا ہے اور اس سُود سے بھی منع کیا ہے جو غریب آدمی اپنی غربت سے تنگ آکر کسی صاحب ِاستطاعت سے قرض لینے کے بعد اسے ادا کرتا ہے اور نہ صرف ایسا سُود دینے سے روکا ہے بلکہ لینے سے بھی منع کیا ہے اور نہ صرف سود لینے دینے سے منع کیا ہے بلکہ گواہی دینے والوں اور معاہدہ لکھنے والوں کو بھی مجرم
Page 509
قرار دیا ہے.تاجر پیشہ لوگوں کے سُود کے متعلق تو جب کوئی شخص سوال کرے کہ مثلاً اس کے پا س دس ہزار روپیہ ہے اور وہ اس سے دس لاکھ کما سکتا ہے.اگر وہ بینکوں یا دوسرے افراد سے روپیہ لے کر اسے ترقی نہ دے تو کیا کرے؟ ہم اسے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صبر کرے دس ہزار روپیہ اس کے لئے کافی ہے اسی پرگذارہ کرتا رہے.مگر جس وقت یہ سوال پیش کیا جائے کہ ایک غریب آدمی بھوک سے مررہا ہے.کھیتی اس کی نہیں ہوئی.اناج اس کے گھر میں نہیں آیا.بارشیں وقت پر نہیں ہوئیں.ایسی صورت میں اگر وہ اپنی زمین کے لئے روپیہ مانگتا ہے تو بغیر سُود کے لوگ اسے نہیں دیتے.اب وہ کیا کرے؟ اگر وہ بیل نہ خریدے گا تو کھیتی کا کام کس طرح کرے گا یا عمدہ بیج نہ لے گا تو وہ اور اس کے بیوی بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اس کے لئے ایک ہی صورت ہے کہ وہ روپیہ قرض لے مگر جب لوگ اسے بغیر سُود کے قرض نہ دیں تو وہ کیا کرے؟ جب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور درحقیقت یہی وہ سُود ہے جس کے حالات اور کوائف سننے کے بعد انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کیا جواب دے؟ مال دار آدمی کو تو ہم فوراً یہ جواب دے سکتے ہیں کہ سُود پر روپیہ مت دو.اگر تمہارے پاس دس ہزار روپیہ ہے تو اسی پر کفایت کرو.مگر ایک غریب آدمی کو ہم یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسی حالت پر کفایت کرو.اس کو تو ایک ہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھوکے رہو اور مرجائو مگر یہ کوئی ایسا معقول جواب نہیں.جس سے ہمارے نفس کو تسلّی ہو.یا سائل کے دل کو اطمینان حاصل ہو.پس ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے اس کا کیا حل رکھا ہے؟ اس نقطہ ٔ نگاہ سے اگر ہم اسلامی تعلیم پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی تو ایسا ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ نہیں ہوتا مگر جائیداد ہوتی ہے.اس کے لئے تو یہ صورت ہے کہ وہ جائیداد رہن رکھے اور روپیہ لے لے مگر ایک ایسا غریب ہوتا ہے جس کے پاس جائیداد بھی نہیں ہوتی جسے وہ رہن رکھ سکے یا اگر جائیداد ہوتی ہے تو وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اگر وہ اسے رہن رکھ دے تو اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے.مثلاً زمیندار ہے اگر وہ اپنی زمین رہن رکھ دیتا ہے تو وہ کھیتی باڑی کہاں کرے گا؟ اپنے مکان کی چھت یا صحن میں تو وہ کر نہیں سکتا.ان حالات میں اسلام نے یہ رکھا ہے کہ ایک طرف تو اس نے امراء پر ٹیکس لگا دیا جس سے غرباء کی امدا د کی جا سکتی ہے اور دوسری طرف اس نے یہ کہا ہے کہ جب ٹیکس سے بھی کسی غریب کی ضرورت پوری نہ ہو تو اس کے دوست واقف کار یا محلّہ والے اسے قرض حسنہ دیں.اور فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ کے ماتحت کشائش تک اسے واپسی کی مہلت دیں تاکہ وہ اطمینان سے اپنی حالت درست کر سکے.یہ صورت ایسی ہے جس پر اسے سُود پر روپیہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس کی احتیاج پوری ہو جاتی ہے.
Page 510
وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ آج کل سُود کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی وہ جھوٹ بولتے ہیں.صحابہؓ کے زمانہ میں جبکہ دو دو کروڑ روپیہ ایک ایک شخص کے پاس ہوتا تھا (اسد الغابۃ ،عبد الرحمٰن بن عوف)کیا سُودی کاروبار ہوا کرتا تھا؟ سود کو تو وہ حرام سمجھتے تھے.پس یہ غلط ہے کہ سُود کے بغیر مال میں ترقی نہیں ہو سکتی.پھر اسلام نے اگر ایک طرف سُود سے منع کیا ہے تو دوسری طرف زکوٰۃ اور وراثت کے طریق کو جاری کیا ہے.اس ذریعہ سے دولت کسی خاص خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی بلکہ جو محنت کرے وہی مال دار ہو سکتا ہے اور غریبوں کے راستہ میں کوئی روک نہیں رہتی.غرض سُود کی حرمت کا مسئلہ ایک نہایت ہی حکیمانہ مسئلہ ہے اور اسلام نے اسے ایسا ناپسند کیا ہے کہ جو شخص سُود لے اس کے اس فعل کو وہ خدا تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ٹھہراتا ہے.گویا اسے بغاوت کے جرم میں داخل کرتا ہےاور جس طرح باغی ملک پر بادشاہ چڑھائی کرتے ہیں اسی طرح سُود لینے والوں کے متعلق فرماتا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہیں آئو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جائو کیونکہ تم نے اس کی بغاوت کی ہے.کہا جاتا ہے کہ اگر سُود حرام ہے تو پھر موجودہ زمانہ میں اسلام کی اس تعلیم پر کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے؟ سویاد رکھنا چاہیے کہ دین ایک نظام کا نام ہوتا ہے اور یہ نظام اسی صورت میں نیک نتیجہ پیدا کر سکتا ہے جب وہ اپنی مکمل صورت میں قائم ہو.ادھوری صورت میں اس کی پوری شان ظاہر نہیں ہو سکتی.جیسا کہ آج کل جب لوگوں کو سود کے خلاف کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر تو گذارہ ہی نہیں ہو سکتا.اس سے ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس زمانہ میں سوسائٹی اس قدر گندی ہو گئی ہے کہ انسان سود لینے پر مجبور ہو جاتا ہے بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سود ہی مصیبت کے وقت کا علاج ہے.حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سود انسان کی مشکلات کا علاج نہیں بلکہ وہ ایک مرض ہے جسے انسان نے خود پیدا کیا ہے اور اسلام میں اس کا علاج موجود ہے.لیکن وہ علاج ایک نظام کے ساتھ وابستہ ہے.جب تک اس نظام کو قائم نہ کیا جائے اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جس طرح ایک مکان کی چاردیواری اور چھت اور دروازے اور کھڑکیاں جب تک کامل نہ ہوں وہ مکان حفاظت کا موجب نہیں ہو سکتا.اگر اسلام کی ساری تعلیم کو قائم کیا جائے تو سود کی ضرورت ہی نہیں رہتی اور سود کی مضرتوں سے بھی دنیا نجات پا جاتی ہے.سود کی ضرورت مندرجہ ذیل اسباب کی وجہ سے ہوتی ہے.(۱) غریب انسان اپنے گذارہ کے لئے قرض لیتا ہے.(۲) تاجر صنّاع یا زمیندار اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے قرض لیتا ہے.
Page 511
۳) ایک صاحبِ جائیداد مصیبت زدہ جس کے پاس نقد روپیہ موجود نہیں کسی ناگہانی آفت سے بچنے کے لئے قرض لیتا ہے.(۱) ظاہر ہے کہ غریب انسان جو آٹھ روپے کما نہیں سکتا وہ آٹھ روپے سود پر لے کر نو کہاں سے ادا کرے گا؟ چنانچہ کسانوں کی موجودہ حالت اس حماقت کو کلّی طور پر ظاہر کر رہی ہے.ایک مرے ہوئے انسان کو مارنا اتنہا درجہ کا ظلم ہے.جو پہلے ہی مررہا ہے اس پر اور بوجھ لاد دینے کا کیا مطلب ہوا.آخر اس ظلم کے نتیجہ میں ایک اور ظلم پیدا ہوتا ہے.یعنی جب مقروض قرضہ نہیں دے سکتے تو وہ قرضہ سے کلّی طور پر انکار کر دیتے ہیں.(۲) تاجر یا صنّاع یا زمیندار اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لئے قرض لیتا ہے.زمیندار کی صورت میں اگر یہ قرض جائیداد کی بہتری کے لئے لیا گیا ہو تو اسلام نے رہن کی صورت کو جائز رکھا ہے.اس تدبیر سے اس نے ایک طرف تو لوگوں کو اتنا قرض اٹھانے سے جسے ادا کرنا ان کی طاقت سے باہر ہو روک دیا ہے.اور دوسری طرف جائز ضرورت کے پورا کرنے کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے.ایک تاجر اور صنّاع کے لئے دوسرے لوگوں کو شریک کار کرنے کا راستہ کھلا ہے.اگر اسے سود سے کاروبار بڑھانے کی اجازت دی جائے اور وہ اپنی تجارتی کوشش میں ناکام رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ دوسرے لوگوں کا روپیہ ضائع جائے گا اور اگر کامیاب ہو تو بے انتہا دولت ایک ہاتھ میں جمع ہو جائے گی جو انصاف اور ضروریاتِ تمدن دونوں کے خلاف ہے.(۳) تیسری صورت ایسی ہے کہ جسے ایک حد تک جائز قرار دیا جا سکتا ہے.کیونکہ اس پر نہ وہ اعتراض پڑتا ہے جو پہلی صورت پر پڑتا تھا کہ یہ دے گا کہاں سے.اور نہ وہ اعتراض پڑتا ہے جو دوسری صورت پر پڑتا تھا.یعنی یہ کیا حق رکھتا ہے کہ سب دنیا کی دولت اپنی ذہانت سے سمیٹ کر اپنے گھر میں جمع کر لے؟ کیونکہ اس صورت میں ایک ایسا شخص قرض لیتا ہے جس کے پاس جائیداد ہے یا قابلیت کمانے کی موجود ہے.لیکن ایک ناگہانی آفت کی وجہ سے اسے ایک وقت میں اتنا روپیہ دینا پڑ گیا ہے جو اس کے پاس جمع نہیں.بظاہر عقل کہتی ہے کہ اسے سو د پر قرض لینے کی اجازت ہونی چاہیے.اس کو سود پر روپیہ قرض دینا ظلم بھی نہیں کیونکہ یہ صاحبِ حیثیت ہے اور یہ لوگوں کے روپیہ سے کھیلتا بھی نہیں کیونکہ اس کے پاس جائیداد ہے یا وہ نوکری پیشہ ہے جو اس کے قرض کے ادا ہونے کے لئے کافی ضمانت ہے.لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے شخص کو سود کی اجازت دے کر سود کا دروازہ کھول دینا زیادہ اچھا ہے یا ایسے شخص کے
Page 512
لئے کوئی دوسری صورت کھولنا؟ یقیناً اگر اس شخص کو اجازت ملے تو دوسری دونوں قسم کے لوگ اس کی مثال پر اپنے لئے بھی سود لینے کا فتویٰ دیں گے.اور یہ لعنت دنیا میں قائم رہے گی.پس اس کے لئے بھی کوئی اور ہی راستہ کھولنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے.اسلام نے ان تمام باتوں کو مدنظر رکھ کر ایک مفصل تعلیم دی ہے.اس تعلیم کا مغز یہ ہے کہ (۱) ہر شخص کو کھانا کپڑا مکان اور علم میسّر ہونا چاہیے.(۲) کسی ایک شخص کے پاس بے انتہا دولت جمع نہیں ہونی چاہیے.(۳) روپیہ پیسہ کسی کے پاس جمع نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے چکر کھاتے رہنا چاہیے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں.(۴) جن کو جائز ضرورتیں پیش آئیں ان کے پورا کرنے کا سامان کرنا حکومت اور سوسائٹی کے ذمہ ہے.نمبر۲ کی شق کے ماتحت اس نے تجارتی سود کو منع کیا ہے.کیونکہ بے انتہا دولت ہمیشہ سود پر روپیہ لینے سے جمع ہوتی ہے اور اس طرح انسان دوسروں کے روپیہ سے ایک جؤا کھیلتا ہے.اگر کامیاب ہوا تو کروڑپتی ہو گیا اور اگر ہارا تو اس کا روپیہ تو تھا نہیں.قرض خواہ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ قید کرا دیں گے.اس کی دوسری شق کے ماتحت اس نے تقسیم جائیداد کا حکم دیا ہے.یعنی ہر شخص کی جائیداد کو اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا ضروری قرار دیا ہے.یہ جائز نہیں رکھا کہ کوئی شخص صرف ایک لڑکے کو جائیداد دے دے تاکہ جو کچھ بھی اس شخص نے کمایا ہے وہ ایک ہی ہاتھ میں جمع رہ کر ہمیشہ کے لئے ایک خاندان کے بعض افراد کو فوقیت نہ دے دے.نمبر اوّل کے ماتحت اس نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ سب کے لئے کھانا کپڑا مکان وغیرہ مہیا کرے.اور اس کے لئے زکوٰۃ اور خراج وغیرہ کا سلسلہ جاری کیا ہے اور افرا د پر صدقہ واجب کیا ہے.نمبر۳ کے لئے اس نے ورثہ اور زکوٰۃ کا سلسلہ جاری کیا ہے اور سود سے منع کیا ہے.اور نمبر۴ کے لئے بھی زکوٰۃ اور صدقات کا سلسلہ اور رہن باقبضہ یا بیع سلم کا سلسلہ جاری کیا ہے.غرض ان اصول پر اس نے ایک مکمل نظام تیار کیا ہے.اگر یہ مکمل نظام دنیا میں جاری کیا جائے اور پھر کوئی نقص رہ جائے تب تو اسلام کی تعلیم پر اعتراض ہو سکتا ہے.ورنہ نظام تو مغربی جاری ہو اور اسلام پر اعتراض ہو کہ اس نے سود سے منع کر کے اس کا علاج کیا بتایا ہے ایک لغو اور بیہودہ فعل ہے.يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ.جیسا کہ حلِّ لغات میں بتایا جا چکا ہے اس جگہ مسّ سے مراد جنون ہے اور جنون کے نتیجہ میں انسانی حرکات میں بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے اور سوچنے اور غور و فکر سے کام لینے کا مادہ اس میں
Page 513
نہیں رہتا.پس مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے کام اس طرح ہوتے ہیں جس طرح ایسا شخص جسے جنون کی بیماری نے ستایا ہوا ہو کھڑا ہوتا ہے.یعنی جس طرح اس میں وقار نہیں ہوتا اور سرعت اور بے پرواہی ہوتی ہے یہی حال سود خواروں کا ہوتا ہے.ان کے کاموں میں بھی ناواجب سرعت پیدا ہو جاتی ہے اور پرواہ اور احتیاط کم ہو جاتی ہے.چنانچہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سودی کا روبار کرنے والے لوگ ایسے فتنے پیدا کرتے رہتے ہیں جن کے نتیجہ میں لڑائی ہو.اور ان کا روپیہ صرف ہو گویا جس طرح ایک مجنون نتیجہ دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا اسی طرح سود پر روپیہ دینے والا سود پر روپیہ دیتا چلا جاتا ہے اور یہ سوچتا نہیں کہ اس کا کیا انجام ہو گا؟ اسے صرف یہ دھت ہوتی ہے کہ کوئی فتنہ پیدا ہو اور لوگ ہم سے سودی قرضہ لیں اور اس طرح ہمارا مال بڑھے.پھر اس سے بڑھ کر بڑی بڑی حکومتوں کو بھی اپنی طاقت سے بڑھ کر سود پر قرض لینے کی جرأت ہو جاتی ہے.اور وہ عواقب سے لاپرواہ ہو کر خون ریز جنگیں شروع کر دیتی ہیں.درحقیقت ایسی لمبی لڑائیاں جو قوموں کی قوموں کو پیس ڈالتی ہیں.لاکھوں عورتوں کو بیوہ اور کروڑوں بچوں کو یتیم بنا دیتی ہیں.جو لاکھوں بیٹوں کو برباد اور لاکھوں باپوں کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں وہ تبھی جاری رہ سکتی ہیں جبکہ سود کے ذریعہ مالی حالت کو قائم رکھا جائے.پہلی جنگ عظیم میں سات کروڑ روپیہ یومیہ صرف گورنمنٹ انگریزی کا خرچ ہوتا تھا اور اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ جرمنی کا خرچ ہوتا تھا.اگر سود کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو جرمنی اس خرچ کو ایک سال تک بھی برداشت نہ کر سکتا اور اس کا سارا اندوختہ تھوڑی مدت میں ختم ہو جاتا.پھر اس نے کیا کیا؟ یہی کہ سود کے ذریعہ کئی سال تک خرچ چلاتا رہا.پھر لڑائی کی بنیاد بھی سود ہی کی وجہ سے پڑی.یہ ٹھیک ہے کہ اتحادی حکومتوں نے دفاعی طور پر جنگ کی.لیکن جرمنی کو کس چیز نے لڑائی چھیڑنے کی جرأت دلائی.اسی سود نے.وہ سمجھتا تھا کہ اگر جنگ شروع ہو گئی تو سود کے ذریعہ میں جس قدر روپیہ چاہوں گا حاصل کرلوں گا اور جنگ جاری رکھ سکوں گا.اگر سود کا دروازہ بند ہوتا تو اس قدر عظیم الشان جنگ جاری رکھنے کا اسے خیال ہی نہ آتا اور اگر براہ راست جرمنوں پر ٹیکس پڑتے تو وہ ایک سال بھی لڑائی جاری نہ رکھ سکتے اور فوراً ملک میں شور پڑ جاتا کہ ہم اس قدر بوجھ برداشت نہیں کر سکتے.لیکن سود کے ذریعہ روپیہ لے کر لوگوں کو اس بوجھ سے غافل رکھا جاتا ہے جو جنگ کے لمبا کرنے کی وجہ سے ان پر پڑتا ہے.پس سود لڑائی کا ایک بھاری سبب ہے.یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام جنگ کے بعد سود کا بھی ذکر فرما دیا کیونکہ سود کا جنگ کے ساتھ گہرا تعلق ہے.اس کے بعد فرماتا ہے.ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا.ان کا ربٰو کھانا اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیںیہ بھی ایک تجارت ہے.اللہ تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے.وَ اَحَلَّ
Page 514
الرِّبٰوا.تمہارے نزدیک تو یہ دونوں برابر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یکساں قرار نہیں دیتا بلکہ وہ ان میں سے بیع کو جائز قرار دیتا ہے اور ربوٰ کو ناجائز.پس اس کا ایک چیز کو جائز اور دوسری کو ناجائزقرار دینا صاف بتاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں اور خدا تعالیٰ نے جو اس سے منع کیا ہے تو آخر کوئی حکمت ہوگی اور وہ حکمت وہی ہے جو پہلی آیت میں بیان ہو چکی ہے.اصل بات یہ ہے کہ اسلام جس تمدن کو قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد دوسروں سے نیک سلوک کرنے اور غرباء کی ترقی پر رکھی گئی ہے.لیکن سودی کا روبار کرنے والے حسن سلوک کو جانتے ہی نہیں صرف روپیہ کی زیادتی ان کے مد نظر ہوتی ہے خواہ دوسرے کا گلا گھونٹ کر کی جائے.پس چونکہ اس ذریعہ سے دوسروں سے نیک سلوک کرنے اور غرباء کو ابھارنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جنگوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اس لئے اسلام نے اس کی کلّی طور پر ممانعت فرما دی.لیکن مکان یا دوکان کا کرایہ ایک علیحدہ چیز ہے.کرایہ اس لئے لیا جاتا ہے کہ مکان یاد وکان کے گرنے کا امکان ہو سکتا ہے اور اس کی مرمت کے لئے مالک مکان کے پاس کچھ نہ کچھ روپیہ ہونا ضروری ہے.اسی طرح تجارت بھی ایک علیحدہ چیز ہے.کیونکہ تجارت میں ایک شخص اپنے مال کا دوسرے کے مال سے تبادلہ کرتا ہے.پس بیع اور ربوٰ کو ایک چیز قرار دینا نادانی ہے.اس کے بعد فرماتا ہے فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ١ؕ وَ اَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ جس شخص کے پاس اس کے ربّ کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات پہنچ جائے اور وہ اسے سن کر اس کی خلاف ورزی سے باز آجائے تو پھر ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم اس کی سابقہ کوتاہیوں پر اس سے کوئی باز پرس نہیں کرتے.پس تم بھی ایسے لوگوں کامعاملہ حوالہ بخدا کیا کرو اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا کرو.ہاں اگر کوئی شخص توبہ کے بعد پھر وہی کام کرنے لگ جائے تو ایسا شخص ضرور سزا کا مستحق ہو گا.یہاں اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ١ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سود اور خریدوفروخت میں کوئی فرق نہیں مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ان میں کوئی فرق نہ ہوتا اور دونوں ایک جیسے ہوتے تو خدا تعالیٰ ان میں سے ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام کیوں قرار دیتا اور پھر باز آنےوالوں کو معاف کیوں کرتا اور جو معافی کے بعد دوبارہ سود لینا شروع کر دیں انہیں سزا کیوں دیتا ؟ یہ بات بتاتی ہے کہ بیع اور ربوٰا ایک جیسے نہیں.ربوٰا کا لازمی نتیجہ آگ ہے خواہ وہ لڑائی کی صورت میں بھڑک اُٹھے یافتنہ وفساد کے رنگ میں ظاہر ہو.مگر بیع کا یہ نتیجہ نہیں ہوتا اور پھر ربوٰ کا یہ نقصان عارضی نہیں بلکہ جب تک یہ لعنت دنیا پر مستولی رہے گی فتنہ و فساد کی آگ بھی بھڑکتی رہے
Page 515
گی.اسی کی طرف ھُمْ فِیْھَا خٰلِدُوْنَ میں اشارہ کیا گیا ہے.ترتیب و ربط: چونکہ گذشتہ آیات میں خدا تعالیٰ کی راہ میں مال دینے کا ذکر تھا اس لئے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ کیوں نہ سود پر روپیہ دیا جائے تاکہ غرباء کا بھی کام چل جائےاور روپیہ دینے والے بھی شوق سے روپیہ دے دیا کریں.اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سود لینے والوں کی حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ گویا ان کو جنون ہو گیا ہے.یعنی وہ خون چوسنے والی جونکیں بن جاتے ہیں.نہ ان میں سوچنے اور سمجھنے کی قوت رہتی ہے اور نہ ہمدردی اور مواخات کا کوئی جذبہ ہوتا ہے.پھر سود سے انسان کاہل اور سست ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اتنی آمدنی تو ضرور ہو جائے گی کوئی اور کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان محنت کرے اور اپنے آپ کو ملک اور قوم کے لئے مفید وجود بنائے.اسی طرح صدقات کے بعد سود کا ذکر اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنا مال خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑنے کو تیا رہو جائے گا وہ بےگانہ مال یعنی سود بھی آسانی سے چھوڑنے کے لئے تیار ہو سکتا ہے.يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰتِ١ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ اللہ سود کو مٹائے گا اور صدقوں کو بڑھائے گا.اور اللہ( تعالیٰ )ہر كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ۰۰۲۷۷ بڑے کافر (اور) بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا.حلّ لُغات.یَمْحَقُ مَحَقَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں اَبْطَلَہٗ وَ مَحَاہُ اسے باطل کر دیا اور مٹادیا.اور مَحَقَ فُـلَانًا کے معنے ہیں اَھْلَکَہٗ.اسے تباہ کر دیا.اور مَحَقَ اللّٰہُ الشَّیْءَ کے معنے ہیں نَقَصَہٗ وَ ذَھَبَ بِبَرَکَتِہٖ.اللہ تعالیٰ نے اسے کم کر دیا اور اس کی برکت کو لے گیا.(اقرب) یُرْبیْ اَرْبَی الشَّیْءَ کے معنے ہیں جَعَلَہٗ یَرْبُوْا اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا دیا.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے.اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا.یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ترقی عطا فرمائے گا جو سود سے پرہیز کریں گے اور صدقات پر زور دیں گے.اس میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب اسلام کی تعلیم اپنی مکمل صورت میں دنیا میں قائم کی جائے گی.اور ربوٰا جسے مال کو بڑھانے والا قرار دیا جاتا ہے وہ مٹا دیا جائے گا اور صدقات جنہیں مال کو گھٹانے والا قرار دیا جاتا ہے ان کی بے انتہا زیادتی
Page 516
ہوگی.گویا پرانے نظام کو بدل کر ایک نیا نظام قائم کیا جائے گا اور قرآن اور اسلام کی حکومت دنیا میں قائم کی جائے گی اور یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے وقوع میں آئے گا.اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اور مناسب حال عمل کرتے ہیں.اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں.ان کے لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ١ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۰۰۲۷۸ لئے ان ربّ کے پاس یقیناً ان کا اجر (محفوظ )ہے.اور انہیں نہ (تو) کسی قسم کا خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے.تفسیر.چونکہ پیچھے صدقات پر بہت زور دیا گیا ہے اس لئے ممکن تھا کہ کوئی شخص یہ خیال کر لیتا کہ صرف صدقہ دے دینا ہی کافی ہے اسی سے نجات ہو جائے گی.اللہ تعالیٰ اس شبہ کے ازالہ کے لئے فرماتا ہے کہ ترکِ ربوٰا اور صدقات کا دینا ہی کافی نہیں بلکہ ہر قسم کے اعمال صالحہ کی بجاآوری اور نمازوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ضروری ہے.صرف ایک پہلو پر زور دے کر تم نجات حاصل نہیں کر سکتے.اس میں ان لوگوں کی غلطی کا ازالہ بھی کیا گیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لئے صرف منہ سے لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کہہ دینا کافی ہے اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں.فرمایا.تمہارا یہ خیال غلط ہے.جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح اور اقامتِ صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ نہ ہو اور تعلق باللہ اور شفقت علیٰ خلق اللہ کے لحاظ سے تمہارے ایمان کی تکمیل نہ ہو اس وقت تک تمہیں نجات میسر نہیں آسکتی.يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰۤوا اے ایمان دارو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو.اور اگر تم مومن ہو تو سود (کے حساب) میں سے جو کچھ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۰۰۲۷۸فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ باقی ہو اسے چھوڑ دو.اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے (برپا ہونے والی) جنگ کا
Page 517
مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ١ۚ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ یقین کر لو.اور اگر تم (سود سے)توبہ کر لو تو (کوئی اتنا نقصان نہیں کیونکہ) تمہارا رأس المال تمہارے لئے وصول کرنا اَمْوَالِكُمْ١ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ۰۰۲۸۰ جائز ہے.(اس صورت میں )نہ تم (کسی پر )ظلم کرو گے اورنہ تم پر ظلم ہوگا.حلّ لُغات.فَاْذَنُوْا اَذِنَ بِالشَّیْءِ کے معنے ہیں عَلِمَہٗ اسے جان لیا.پس فَاْذَنُوْا کے معنے ہیں تم جان لو.یقین کر لو.(اقرب) رَئُ وْسُ اَمْوَالِکُمْ رَأْسُ الْمَال اُس اصل مال کو کہتے ہیں.جس پر کوئی نفع نہ ہو.چنانچہ کہتے ہیں.اَقْرَضَنِیْ عَشْرَۃً بِرَءُ وْسِھَا اَیْ قَرْضًا لَارِبْـحَ فِیْہِ فَیَرُدَّ عَلَیْہِ رَاْسَ الْمَالِ.یعنی اس نے مجھے دس دینار بغیر اس کے کہ ان پر کچھ اور نفع مقرر کرتا قرض دیئے.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے.اے مسلمانو!اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو تم خدا اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائو.یہ ایک بہت بڑی تنبیہہ ہے جو مسلمانوں کوکی گئی مگر افسوس ہے کہ انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی اور پھر اس کا خطرناک نتیجہ بھی انہوں نے دیکھا.ان کی زمینیں اور جائیداد یں چھن کر دوسروں کے پاس چلی گئیں.اور وہ مفلس اور قلاش ہو گئے بلکہ مسلمانوں کی گذشتہ دَور میں جس قدر سلطنتیں تباہ ہوئیں ان کی تباہی کی بڑی وجہ بھی یہی ہوئی.وہ اکثر سود لے کر یا سود دے کر ہی تباہ ہوئی ہیں.اگر انہوں نے سودی روپیہ لیا تو روپیہ دینے والی سلطنتوں نے ان کے ملک میں آہستہ آہستہ اپنا تسلّط جمانا شروع کیا.کبھی ریلوں کا ٹھیکہ لیا.کبھی کانوں کو کفالت میں رکھا.کبھی کسی اور چیز پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ تمام ملک پر چھا گئے.پھر اگر انہوں نے سود پر قرض دیا.تو جب کبھی سلطنتوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوئی تو وہ ارکانِ سلطنت جنہوں نے اپنا تمام سرمایہ غیروں کو سود پر دیا ہوا تھا اپنے قرض داروں کے طرف دار ہو گئے تاکہ ان کا روپیہ نہ مارا جائے.چنانچہ لکھنؤ اور اودھؔ والوں نے ایسا ہی کیا.انہوں نے کسی کو سود دیا نہیں بلکہ خود لینا چاہا اور بہت ساروپیہ انگریزی بینکوں میں جمع کرا دیا.جب لکھنؤ پر حملہ ہوا تو بڑے بڑے رئیسوں کو انگریزوں نے کہلا بھیجا کہ اگر تم ذرا بھی مخالفت کروگے تو تمہارا تمام مال جو ہمارےبینکوں میںہے ضبط کر لیا جائے گا.اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور ایک شخص بھی نواب کی تائید میں نہ
Page 518
اُٹھا.ایک ڈاکو کے قتل پر بھی بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن لکھنؤ کے نواب کے قتل پر ایک شخص بھی انگریزوں کے مقابلہ کے لئے تیار نہ ہوا.غرض سیاسی طور پر سود کا لینا بھی مسلمانوں کے حق میں سخت نقصان دہ ثابت ہوا.کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کی.یوں تو دوسری حکومتیں بھی سود لیتی اور دیتی رہی ہیں مگر ان کو اس سے وہ نقصان نہیں پہنچا جو مسلمانوں کو ہوا.اس کی ایک روحانی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کو اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر اس طرح چھوڑ رکھا ہے جس طرح ایک باپ اپنے بچہ کو عاق کر دیتا ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا.لیکن مسلمان اس بچہ کی طرح ہیں جس سے اس کے ماں باپ کو پیار ہوتا ہے.پس مسلمان جب بھی احکامِ الٰہیہ کی خلاف ورزی کریں گے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح تھپڑ پڑے گا جس طرح ایک باپ اپنے بچہ کو تھپڑ مارتا ہے.کیونکہ وہ اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے.اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرلے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق منقطع کر لے گا اور دنیا میں اس کی اِصلاح کے لئے اپنا ہاتھ نہیں بڑھائے گا.مگر مسلمانوں کی تو یہ حالت ہے کہ ایک طرف تو وہ بڑے زور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی صداقت کا اقرار کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے احکام کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں.اور یہ صورت ایسی ہے جس میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان کی گرفت کے لئے بڑھتا ہے اور انہیں وقتاً فوقتاً فہمائش کرتا رہتا ہے.ورنہ محض کفر پر اس دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں عذاب دیا جاتا ہے اور ایسا کافر جو کسی کو دُکھ نہیں دیتا اور اپنے خیال کی بنا پر اپنے مذہب پر عمل کرتا رہتا ہے.اس سے یہاں کوئی پرسش نہیں کی جاتی.مگر وہ لوگ جو اسلام کو قبول کرتے ہوئے پھر بھی اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتے ان کو یہاں بھی سزا دی جاتی ہے تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں.اور ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق کلّی طور پر منقطع نہ ہو.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دوسری سلطنتوں پر بھی مختلف اوقات میں زوال آئے.مگر وہ زوال صرف سیاسی رنگ کے تھے.لیکن اسلامی سلطنتیں محض اس لئے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے سود پر قرض لیا یا دیا اور اس طرح اسلامی احکام کی خلاف ورزی کی.فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سُود دے یا لے.اس سے قومی طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے.کیونکہ وہ باغی ہے اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے ایک واضح حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے.وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حکم صرف ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے سود پر روپیہ دیا ہوا تھا مگر پھر انہوں نے توبہ کر لی.اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اگر آئندہ کے لئے تم اس
Page 519
فعل سے توبہ کر لو تو رأس المال وصول کرنا تمہارے لئے جائز ہے.گو ممکن ہے کہ اس عرصہ میں تم اصل مال سے بھی زیادہ سود لے چکے ہو.وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ١ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا اور اگر (کوئی )مقروض تنگ حال ہو کر آئے تو آسودگی (حاصل ہونے) تک (اسے) مہلت دینی ہوگی.اور اگرتم خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۰۰۲۸۱وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو جان لو کہ تمہارا (اس شخص کو رأس المال بھی) صدقہ (کے طور پر ) دےدینا سب سے اچھا (کام) فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ١۫ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ ہے.اور اس دن سے کہ جس میں تمہیںاللہ کی طرف لوٹایا جائے گا ڈرو.پھر ہر ایک شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہو گا پورا لَا يُظْلَمُوْنَؒ۰۰۲۸۲ (پورا)دے دیا جائے گا.اور ان پر (کوئی )ظلم نہیں کیا جائے گا.حلّ لُغات.اَلنَّظِرَۃُ کے معنے ہیں اَلتَّأْخِیْرُ وَ الْاِمْھَالُ فِی الْاَمْرِ.ادائیگی کے لئے مہلت دینا.(اقرب) تفسیر.فرماتا ہے.آج اگر تم لوگوں سے حسنِ سلوک کرو گے اور اپنے قرضوں کی وصولی میں نرمی سے کام لو گے تو یاد رکھو ایک دن تمہارا بھی حساب ہو گا اس دن تم سے بھی اچھا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے گناہوں سے درگذر کیا جائے گالیکن اگر آج تم نیک سلوک نہیں کروگے تو اس دن تم سے بھی کوئی نیک سلوک نہیں کیا جائے گا.یہ وہی حکم ہے جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے باربار توجہ دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ تم دنیا میں رحم سے کام لوتاکہ آسمان پر تمہارا خدابھی تم سے رحم کا سلوک کرے(ترمذی کتاب البرّ و الصّلۃ باب ما جاء فی رحمة الناس).
Page 520
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ اے ایمان دارو! جب تم کسی دوسرے سے کسی مقررہ میعاد کے لئے قرض لو مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ١ؕ وَ لْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ١۪ تو اسے لکھ لو.اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان (طے شدہ معاہدہ کو) انصاف کے ساتھ لکھ دے.وَ لَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ١ۚ وَ اور کوئی کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ نے اسے (لکھنا)سکھایا ہے.پس چاہیے کہ وہ (ضرور )لکھے.لْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَ لَا يَبْخَسْ اور تحریر وہ لکھوائے جس کے ذمہ حق ہو.اور چاہیے کہ وہ (لکھواتے وقت ) اللہ کا جو اس کا ربّ ہے تقویٰ مدّ نظر رکھے مِنْهُ شَيْـًٔا١ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ اور اس میں سے کچھ (بھی) کم نہ کرے.اور اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے نادان ہو یا کمزور ہو یا (خود) لکھوانے ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ کی قدرت نہ رکھتاہو تو چاہیے کہ (اس کی بجائے) اس کا کار پرداز انصاف کے ساتھ (تحریر)لکھوائے.بِالْعَدْلِ١ؕ وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ١ۚ اور تم اپنے مردوں میں سے (اس موقعہ پر) دو کو گواہ (مقرر ) کر لیا کرو.فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ہاں اگر دونوں (گواہ) مرد نہ ہوں تو (موقعہ کے) گواہوں سے جن لوگوں کو (بطورگواہ) تم پسند کرتے ہو.ان میں سے
Page 521
مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا ایک مرد اور دو عورتیں (گواہ بنا لیا کرو) (دو عورتوں کی شرط اس لئے ہے) تا ان میں سے ایک کے بھول جانے کی الْاُخْرٰى ١ؕ وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا١ؕ وَ لَا تَسْـَٔمُوْۤا صورت میں دونوں میں سے (ہر) ایک دوسری کو (بات) یاد دلائے.اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں.اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ١ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ اور (خواہ )چھوٹا (لین دین)ہویا بڑا ہو تم اسےاس کی میعاد سمیت لکھنے میں سستی نہ کیا کرو.یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ عِنْدَ اللّٰهِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ انصاف والی ہے.اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والی ہے.نیز(تمہارے لئے اس بات کو) قریب تر (کر دینے تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ والی) ہے کہ تم شک میں نہ پڑو(پس لین دین کا لکھنا ضروری ہے) سوائے اس (صورت) کے کہ تجارت دست بدست ہو.جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا١ؕ وَ اَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْ١۪ وَ لَا جسے تم آپس میں (مال اور رقم) لے دے کر (اسی وقت قصہ ختم کر) لیتے ہو.اس صورت میں اس (لین دین)کے نہ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيْدٌ١ؕ۬ وَ اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں.اور جب باہم خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو.اور (یہ امر یاد رہے کہ )نہ کاتب کو بِكُمْ١ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ١ؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ۰۰۲۸۳ تکلیف دی جائے اور نہ گواہ کو.اور اگر تم (ایسا )کروتو یہ (بات ) تم میںنافرمانی (کی علامت)ہو گی.اور چاہیے کہ (تم )اللہ کا تقویٰ اختیار کرو.اور (اگر تم ایسا کرو گے تو) اللہ تمہیں علم دے گا.اور اللہ (تعالیٰ) ہر چیز کو خوب جانتا ہے.حلّ لُغات.تَدَایَنْتُمْ تَدَایَنَ الْقَوْمُ کے معنے ہیں اِسْتَدَانَ بَعْضُھُمْ مِنْ بَعْضٍ.ایک
Page 522
دوسرے سے قرض لیا.(اقرب) یُمْلِلْ اَمْلَلْتُ الْکِتٰبَ عَلَی الْکَاتِبِ اِمْلَالًا وَ اَمْلَیْتُہٗ عَلَیْہِ اِمْلَاءً کے معنے ہیں اَلْقَیْتُہٗ عَلَیْہِ اَیْ قُلْتُ لَہٗ فَکَتَبَ عَلَیَّ.یعنی اَمْلَلْتُ الْکِتَابَ عَلَی الْکَاتِبِ کے یہ معنے ہیں کہ میں نے کاتب کو کچھ مضمون لکھوایا جسے اس نے لکھ لیا.پس یُمْلِلْ کے معنے ہیں لکھوائے.اِملاء بھی اسی میں سے ہے.(اقرب) سَفِیْہٌ کے معنے کم علم اور جاہل کے ہیں.(اقرب)لیکن امام شافعی ؒ نےمُسرف کے معنے کئے ہیں(روح المعانی) اور مجھے بھی یہی پسند ہیں.جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے اَنُؤْمِنُ کَمَا اٰمَنَ السُّفَھَآءُ.(البقرۃ:۱۴) یعنی منافق کہتے ہیں ہم تو انکار کر کے اپنا مال بچاتے اور اسے محفوظ رکھتے ہیں.ان کوکیا معلوم کہ مال کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے ؟ یہ لوگ تو ایمان لا کر اپنا مال تباہ کر لیتے ہیں.تفسیر.اوپر کی آیات میں قومی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ نے سُود بتایا تھا.اب دوسرا سبب قومی تنزل کا یہ بتاتا ہے کہ لین دین کے معاملات میں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا.قرض دیتے وقت تو دوستی اور محبت کے خیال سے نہ واپسی کی کوئی میعاد مقرر کرائی جاتی ہے اور نہ اسے ضبط تحریر میں لایا جاتا ہے اور جب روپیہ واپس آتا دکھائی نہیں دیتا تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ مقدمات تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور تمام دوستی دشمنی میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس کے تعلقات کو خراب مت کرو اور قرض دیتے یا لیتے وقت ہماری ان دو ہدایات کو ملحوظ رکھو.اول یہ کہ جب تم کسی سے قرض لوتو اس قرض کی ادائیگی کا وقت مقرر کر لو.دومؔ روپیہ کا لین دین ضبطِ تحریر میں لے آئو.اس شرط کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس طرح مقروض کو احساس رہتا ہے کہ فلاں وقت سے پہلے پہلے میں نے قرض ادا کرنا ہے اور وہ اس کی ادائیگی کے لئے جدوجہد کرتا رہتا ہے اور پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ قرض لینے والا ایک معیّن میعاد تک اطمینان کی حالت میں رہتا ہے اور اسے یہ خدشہ نہیں رہتا کہ نہ معلوم قرض دینے والا مجھ سے کب اپنے روپیہ کا مطالبہ کر دے ؟غرض اس میں دینے والے کا بھی فائدہ ہے اور لینے والے کا بھی.قرض دینے والے کا فائدہ تو یہ ہے کہ مثلاً ایک مہینے کا وعدہ ہے تو وہ ایک مہینہ کے بعد جا کر طلب کرے گا.یہ نہیں کہ اس کو روز روز پوچھنا پڑے اور قر ض لینے والے کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ قرض لینے لگے گا تو سوچے گا کہ میں جتنے عرصے میں ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں اتنے عرصہ میں ادا بھی کر سکوں گا یا نہیں.اس کے علاوہ یہ شرط اس لئے بھی عاید کی گئی ہے کہ بعض کمزور لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ ہم سُود پر روپیہ اس لئے دیتے ہیں کہ قرض لینے والے کو اس کی ادائیگی کا فکر رہتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جلد اس قرض سے سبکدوش ہو جائوں.لیکن اگر سود نہ لیا
Page 523
جائے تو اسے ادائیگی کا احساس نہیں رہتا.اس وسوسہ کے ازالہ کے لئے فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کو قرض دو.تو معاہدہ لکھوا لیا کرو کہ فلاں وقت کے اندر اندر ادا کردوں گا تاکہ تمہارا روپیہ بھی محفوظ رہے اور دوسرے شخص کو بھی اپنی ذمہ واری کا احساس رہے.لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر قرض اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ہو تو لکھ لیا کرو اور اگراِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى نہ ہو تو بے شک نہ لکھو.اس لئے کہ جب کو ئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو بہر حال ایک اَجَلٍ مُّسَمًّى کے لئے ہی دیتا ہے خواہ وہ میعاد تھوڑی ہو یا بہت.اس کے بعد وہ اسے وصول کرنے کا حقدار ہوتا ہے.یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے دوسرے کو قرض دیا ہو اور پھر اس کے واپس لینے کا اس کے اندر کوئی احساس ہی نہ ہو.ہدیۃً یا امداد کے رنگ میں اگر کسی کو کوئی رقم دی جائے تو وہ ایک علیٰحدہ امر ہے.لیکن جس چیز پر قرض کے لفظ کا اطلاق ہو گا وہ بہرحال اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ہی ہو گی.خواہ زبان سے کوئی میعاد مقرر کی جائے یا نہ کی جائے.ہاں اگر خاص وقت کے لئے قرض نہیں بلکہ یونہی ایک دو گھنٹہ کے لئے یا ایک دو دن کے لئے ہے تو ایسی صورت میں اگر نہ لکھا جائے تو کوئی شرعی گناہ نہیں.افسوس ہے کہ مسلمان ان دونوں باتوں کی پرواہ نہیں کرتے.یعنی نہ تو قرض دیتے وقت دوستی اور محبت کے نقطۂ نگاہ سے کوئی مدت مقرر کرتے ہیں.بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ جب جی چاہے دے دینا اور نہ اسے ضبطِ تحریرمیں لاتے ہیں جس کی وجہ سے بعد میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انہیں اس کے تلخ نتائج سے دوچار ہونا پڑتا ہے.وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.تیسرا حکم یہ دیا کہ لکھنے والا کوئی اور شخص ہو.قرض دینے والا یا لینے والا نہ لکھے بلکہ ایک غیرشخص ہو جو عدل اور انصاف کے ساتھ لکھے.یعنی اپنی طرف سے اس معاہدہ میں کوئی بات نہ ملائے بلکہ وہی کچھ لکھے جس کے لکھنے کا اسے حکم دیا گیا ہے.پھر کاتب کو حکم دیا کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ لکھے یا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے.کَمَا عَلَّمَہٗ کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں.یہ بھی کہ جتنا ہنر اس کو حاصل ہو اس کے مطابق لکھے.اور یہ بھی کہ چونکہ خدا تعالیٰ نے اس پر فضل کیا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے.یہ نہ ہو کہ وہ انکار کر دے اور ضرورت مند قرض نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو.وَلْیُمْلِلِ الَّذِیْ عَلَیْہِ الْحَقُّ.چوتھا حکم یہ دیا کہ جس کے ذمہ حق ہو وہ املاء کر وائے.یعنی روپیہ لینے والے کو چاہیے کہ وہ خود تحریر لکھوائے.اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے.بظاہر تو یہ چاہیے تھا کہ روپیہ دینے والا
Page 524
لکھوائے.مگر یہ حکم نہیں دیا.بلکہ اس کی ذمہ واری قرض لینے والے پر رکھی ہے اورا س کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روپیہ لینے والے کی ضرورت روپیہ مل جانے کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے.وہ اس وقت اپنے اندر خوشی کی ایک لہر محسوس کرتا ہے اور روپیہ کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے.اس لئے ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں ضرورت پوری ہونے پر کہہ دے کہ مجھے تو اس وقت یہ خیال ہی نہ تھا کہ کیا لکھوا رہے ہیں اس لئے اسے کہا کہ وہ خود ہی لکھوائے تاکہ اس کی زبان کا اقرار موجود رہے ورنہ جس نے روپیہ دیا ہوتا ہے وہ توچوکس ہی ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنے پاس سے رقم دی ہوئی ہوتی ہے.اس لئے اس کو تو بہرحال یاد ہی رہتا ہے کہ میں نے اس قدر روپیہ دیا ہوا ہے.دوسری وجہ یہ ہے کہ تحریر اس کے پاس رہے گی جس نے روپیہ دیا ہے.پس اس کے لئے تو موقعہ ہے کہ دیکھ لے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی.مگر لینے والے کے پاس تحریر نہیں رہنی اس لئے اگر اس وقت اس کی پوری توجہ تحریر کی طرف نہ ہو تو اسے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو سکتا ہے.وَ لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا.یہ پانچواں حکم دیا کہ لکھواتے وقت وہ کوئی چیز اس قرض میں سے کم نہ کرے بلکہ اسے صحیح صحیح لکھوائے.اس میں بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرض میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی کیونکہ دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں.پھر لَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا کا کیوں حکم دیا؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض قرض عجیب عجیب شکل میں ہوتے ہیں.جن کو تحریر میں لاتے وقت لوگ ایسے پیچیدہ الفاظ لکھتے ہیں جن کا نتیجہ آخر میں کمی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے.خصوصاً وہ قرض جو لمبی میعاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں.اور مختلف انواع کے ہوں ان کو تحریر میں لاتے وقت کئی قسم کے دھوکے کر لئے جاتے ہیں جیسے حکومتوں کے قرض ہوتے ہیں.چونکہ ایسے لمبے قرضوں میں عموماً معاہدات کے وقت چالاکیاں اور فریب کیے جاتے ہیںاس لئے فرمایاکہ لکھوانے میں دیانت سے کام لو اور ایک حبّہ بھی کم کرنے کی کوشش نہ کرو.فَاِنْ کَانَ الَّذِیْ عَلَیْہِ الْحَقُّ سَفِیْھًا اَوْ ضَعِیْفًا اَوْ لَایَسْتَطِیْعُ اَنْ یُّمِلَّ ھُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّہٗ بِالْعَدْلِ.فرماتا ہے اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے دماغی لحاظ سےاس قابل نہ ہو کہ مالی معاملات کی اہمیت کو سمجھ سکے یا کمزور ہو.مثلاً بچہ ہو یا بہت بوڑھا ہو یا لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو.مثلاً گونگا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے ایک ولی مقرر ہونا چاہیے جو تمام امور پورے عدل اور انصاف کے ساتھ ملکی قانون کے مطابق لکھوائے چونکہ پہلے یہ حکم دیا جا چکا تھا کہ قرض لینے والالکھوائے اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں اس کا ولی اس ذمہ داری کو ادا کرے.
Page 525
وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ.یہ ساتواں حکم دیا کہ اس کے لئے دوگواہ بھی مِنْ رِّجَالِكُمْ بنائے جائیں یعنی اپنے واقف آدمیوں میں سے جن پر تمہیں اعتماد ہو اور جنہیں ضرورت کے وقت تم آسانی سے بلا سکتے ہو.کوئی غیرملکی یا مسافر یا ناواقف آدمی نہ ہوں جن کی گواہی ضائع چلے جانے کا خطرہ ہو ورنہ تم ان کو کہاں تلاش کرو گے.اس کے بعد جو مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ کے الفاظ آتے ہیں ان کا تعلق بھی وَ اسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ سے ہی ہے.ورنہ یہ مطلب نہیں کہ اگر رجال پسند نہ ہوں تو عورتیں ہی گواہ مقرر کر لی جائیں.اس جگہ تَرْضَوْنَ میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ گواہ ایسے ہونے چاہئیں جو فریقین کے پسندیدہ ہوں.یعنی وہ گواہی دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہوں..ایسے نہیں ہونے چاہئیں جنہیں شاہد عادل قرار نہ دیا جا سکے.فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ.یہ آٹھواں حکم دیا کہ اگر دو مرد نہ ملیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لیا کرو.مگر گواہ انہیں کو بنائو جن کو تم پسند کرو.ایک مرد کی بجائے دو عورتیں رکھنے کی وجہ یہ بتائی کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلادے.وہ بھول جائے تویہ یاد دلائے.چونکہ دونوں میں سے ہر ایک بھول سکتی اور ہر ایک یاد کراسکتی ہے.اس لئے لفظ مبہم رکھے ہیں اور اس لئے بھی کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون بھولی ہے؟ اس لئے فرمایاکہ ان میں سے ہر ایک دوسری کو یاد دلا دے.دراصل گھریلو جھگڑوں سے تعلق رکھنے والی باتوں کو تو عورت خوب یاد رکھتی ہے لیکن قضاء سے تعلق رکھنے والے امور کو اپنے ذہن میں زیادہ عمدگی سے محفوظ نہیں رکھ سکتی.اس لئے دوعورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا گیا ہے.اس آیت کی روشنی میں ایک واقعہ کی دو گواہ عورتوں کو بیک وقت قضاء میں بلایا جا سکتا ہے اور قاضی کے سامنے بھی ان میں سے ایک عورت دوسری کو یاد دلا سکتی ہے کہ بہن یہ بات یوں نہیں بلکہ یوں ہے.گویا جس طرح مرد بعض باتوں کا سوچ کر جواب دیتا ہے اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسری کو یاد دلا کر جواب دے سکتی ہیں.پھر جس بات پروہ دونوں اتفاق کریں وہی ان کی گواہی سمجھی جائے گی.مرد کے مقابلہ میں دو عورتوں کی گواہی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ ہر شخص جو کسی کام کا عادی ہوتا ہے وہ بہ نسبت دوسروں کے جو اس کام میں نہ پڑے ہوں زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے.مرد چونکہ لین دین کے معاملات اور مقدمات وغیرہ میں اکثر حصہ لیتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شہادت دینا کتنی بڑی ذمہ داری کا کام ہے.اس لئے وہ تمام واقعات کو احتیاط سے یاد رکھتے اور ہوشیاری سے اپنا بیان لکھواتے ہیں لیکن عورتوں کا نہ تولین دین کے معاملات میں زیادہ دخل ہوتا ہے اور نہ عدالتوں کی کارروائی سے وہ واقف ہوتی ہیں.ان کا دائرہ عمل صرف گھریلو زندگی تک
Page 526
محدود ہوتا ہے.اس لئے ہو سکتا ہے کہ کسی بات کو وہ پورے طور پر یاد نہ رکھ سکیں.اس احتیاط کے پیش نظر ایک مرد کی بجائے دوعورتوں کی گواہی مقرر کی گئی ہے.مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ یہ مِنْ رِّجَالِكُمْ کا بدل ہے بعض نے کہا ہے کہ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاَتٰنِ کی صفت ہے (روح المعانی زیر آیت ھذا).لیکن اَبوحَیّانؔ کا قول ہے کہ یہ اِشْتَشْھِدُوْا سے متعلق ہے اور یہی درست ہے.یعنی اس جگہ اہلیت اور پسندیدگی کی شرط مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہے.صرف مردوں یا صرف عورتوں کے لئے نہیں.وَ لَا يَاْبَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا.یہ نواں حکم دیا کہ جب گواہوں کو گواہی کے لئے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور خواہ کسی فریق کی ناراضگی کا ہی خطرہ ہو پھر بھی سچی سچی بات بیان کر دیں.وَ لَا تَسْـَٔمُوْۤا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰۤى اَجَلِهٖ.اس جگہ اجل کو اجلہٖ کہہ کر پھر پہلے حکم کو دہرا دیا ہے جس کا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّىمیں ذکر کیا گیا تھا.اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر میعادی قرضہ کو نہ لکھو یا صرف مدت کی مقدار لکھ لو اور قرض کو مبہم رہنے دو.بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض بھی لکھ لو اور مدت بھی مقرر کر لو.چونکہ الی کے ایک معنے مع کے بھی ہوتے ہیں.اس لئے اس کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ مدت کو بھی ساتھ ہی لکھ لیا کرو.گویا قرض اس کی ادائیگی کی میعاد اور شہادت سب باتوں کو اکٹھا لکھو تاکہ دوسرے کو خیانت کا موقعہ ہی نہ ملے.ذٰلِکَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰہِ وَ اَقْوَمُ لِلشَّھَادَۃِ فرماتا ہے.یہ بات انصاف کو قائم کرنے والی اور شہادت کو درست رکھنے والی ہے.اگر یہ قانون نہ رکھا جاتا تو نہ تو انصاف قائم ہو سکتا اور نہ ہی شہادت درست رہ سکتی.وَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَرْتَابُوْۤا.اس میں بتایا کہ اس قانون کی اتباع کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دوسرے کی دیانت اور امانت کے متعلق مختلف قسم کے وساوس اور شبہات سے محفوظ رہو گے.اور اپنے روپیہ کے متعلق بھی تمہیں اطمینان رہے گا کہ وہ ضائع نہیں ہو سکتا.اِلَّا اَنْ تَکُوْنَ تِجَارَۃً حَاضِرَۃً تُدِیْرُوْنَھَا بَیْنَکُمْ.فرماتا ہے کہ ہم اس قانون میں ایک استثنیٰ کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اگر ایسی تجارت ہو جو آمنے سامنے کی اور دست بدست ہو جسے تم اِدھر اُدھر چکر دیتے ہو تو ایسی صورت میں اگر تم اسے تحریر میں نہ لائو تو تم پر کوئی گناہ نہیں.کیونکہ وہ دین نہیں.گویا اگر حاضر تجارت ہو اور ایک تاجر دوسرے تاجر کو کہہ دے کہ میرا مال فلاں گو دام میں پڑا ہوا ہے میں ابھی جا کرلے آتا ہوں آپ مجھے اتنا روپیہ دے دیں تو ایسی
Page 527
صورت میں کسی تحریر کے بغیر بھی دوسرے کو روپیہ دے دینے میں کوئی حرج نہیں.تاجروں کو ایسے معاملات روزانہ پیش آتے رہتے ہیں.گو لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَکْتُبُوْھَاکے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تجارت کے وقت لین دین کو نہ لکھنا گناہ تو نہیں لیکن اچھا یہ ہے کہ اس میں بھی رسید کاٹی جائے.جیسا کہ انگریزی فرموں اور تاجروں میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز ان سے خریدی جائے تو ساتھ ہی وہ رسید بھی لکھ دیتے ہیں.اس سے کئی جھگڑے مٹ جاتے ہیں اور کمی بیشی یا چوری وغیرہ کا الزام عاید نہیں ہو سکتا.بہرحال اس جگہ تجارتِ سلم اور تجارتِ نقد کا ذکر کیا گیا ہے.تجارتِ سلم کی صورت میں مال اور مدت کی تعیین لازمی قرار دی گئی ہے اور اس کا لکھنا فرض کیا گیا ہے.اسی طرح اس خرید کی صورت میں بھی کہ مال لے لیا جائے اور رقم کی ادائیگی کا آئندہ وعدہ ہو لیکن جب نقد سودا ہو کہ مال لے لیا اور قیمت دے دی تو لکھنا فرض نہیں رکھا گیا.گو عبارت سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں بھی پسندیدہ یہی ہے کہ تحریر دی جائے.ہاں جب تحریر نہ ہو تو گواہ مقرر کر لے.جیسا کہ وَ اَشْهِدُوْۤا اِذَا تَبَايَعْتُمْسے ظاہر ہے تاکہ بعد میں دوکاندار چوری وغیرہ کا الزام نہ لگا دے اور کوئی فتنہ پیدا نہ ہو.وَلَایُضَآرَّ کَاتِبٌ وَّلَاشَھِیْدٌ.فرمایا گواہ اور کاتب کو خرچ دیئے بغیر عدالتوں میں بلانا ان کے لئے نقصان کا موجب ہے.اس لئے ان کو خرچ دینا تمہارے لئے ضروری ہے.یہ لین دین کے سلسلہ میں گیارھواں حکم دیا کہ معاہد ہ لکھنے والے اور گواہوں کو خرچ دو اور ان کو تکلیف میں نہ ڈالو.اگر ایک کاتب جس کا کام یہ ہے کہ وہ اُجرت پر لکھتا ہے اسے مجبور کیا جائےکہ وہ بلا اجرت کوئی مضمون لکھ کر دے تو یہ اس پر ظلم ہو گا یا مثلاً کوئی شخص اگر کسی اور بڑی ذمہ واری کے کام پر جا رہا ہو تو ایسے شخص کو مجبور کرنا کہ وہی لکھے.یا بلاخرچ آکر گواہی دے اس پر ظلم ہے.وَ اِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ فرماتا ہے اگر تم ان کو دق کروگے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ تم ہمارے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو.اور اطاعت کا جُوآ اپنی گردن سے اُتارتے ہو بِکُمْکے معنے فِیْکُمْ کے ہیں.یعنی یہ بات تمہارے اندر فسق اور خروج عَنِ الطَّاعَۃ کی رُوح پیدا کرنے والی ہو گی.وَ اتَّقُوا اللّٰهَ١ؕ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ فرماتا ہے.یہ تمدنی احکام ہیں جن پر تمہارے معاشرہ کی ترقی کا انحصار ہے اس لئے ان کو ہمیشہ مدّنظر رکھو اور اس بات کو سمجھ لو کہ تم جتنا تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے کا روبار میں اتنی ہی برکت ڈالے گا اور تمہیں اپنے علم سے حصہ عطا فرمائے گا.کیونکہ ترقی کی کوئی راہ اس سے پوشیدہ نہیں.وہ ہرچیز کو خوب جانتا اور سمجھتا ہے.
Page 528
وَ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ١ؕ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو (اس کا قائم مقام ) رہن باقبضہ ہے.فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس اگر تم میں سے کوئی شخص کسی (دوسرے )کو امین جانے اور (اسے کچھ رقم دے دے )تو جسے امین سمجھا گیا ہو اَمَانَتَهٗ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ١ؕ وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ١ؕ وَ مَنْ اسے چاہیے کہ اس کی (یعنی امانت رکھنے والے کی )امانت کو( عند الطلب) واپس کر دے.اور اپنی ربوبیت کرنے يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ١ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌؒ۰۰۲۸۴ والے اللہ کا تقویٰ اختیار کرے.اور تم گواہی کو(کبھی) مت چھپاؤ.اور جو اسے چھپائے وہ یقیناً ایسا (شخص )ہے جس کا دل گنہگار ہے.اور (یاد رکھو کہ )جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے.حلّ لُغات.رِھٰنٌ مصدر بھی ہے.اور رِھْنٌ کی جمع بھی.اور اَلرَّھْنُ کے معنے ہیں.مَا وُضِعَ وَثِیْقَۃً لِلدَّیْنِ.وہ چیز جسے قرضہ حاصل کرنے کے لئے بطور ضمانت رکھا جائے.وَقِیْلَ الرَّھْنُ لُغَۃً اَلْحَبْسُ مُطْلَقًا وَ کَثِیْرًا مَّا یُطْلَقُ عَلَی الشَّیْءِ الْمَرْھُوْنِ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رھن کا لفظ مطلق حبس پر بھی استعمال ہوتا ہے.لیکن زیادہ تر استعمال اس چیز پر ہوتا ہے جسے قرض کے لئے گرو رکھا جائے.(اقرب) اُؤْتُمِنَ اِءْ تَمَنَہٗ کے معنے ہیں عَدَّہٗ اَمِیْنًا اَوِ اتَّخَذَہٗ اَمِیْنًا اسے امین سمجھا یا امین بنا لیا.اِنَّہٗ میں ضمیر شان استعمال ہوئی ہے اور اس کے معنے ہیں ’’بات یہ ہے‘‘.تفسیر فرماتا ہے.اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی کاتب اور وثیقہ نویس نہ ملے تو اس کا قائم مقام رہن باقبضہ ہے.تمہیں چاہیے کہ تم اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس بطور رہن رکھوا دو تاکہ اسے اپنے روپیہ کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ رہے.اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام قرض کے معاملہ میں کتنی احتیاط اور دوراندیشی سے کام لینے کی ہدایت دیتا ہے اور کس طرح قدم قدم پر مومنوں کے اموال اور ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے.اگر ان قواعد کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرض کا انکار کر دے اور اس طرح دوسرے کو مالی لحاظ سے اور
Page 529
اسے خود ایمانی لحاظ سے ناقابلِ تلافی نقصان پہنچے.اسلام اس قسم کے خدشات کا علاج یہ بتاتا ہے کہ قرض کے معاملہ کو اول ایک باقاعدہ معاہدہ کے ذریعہ ضبط تحریر میں لائو جس پر گواہوں کی گواہی بھی ثبت ہو.دوم اگر باقاعدہ تحریر کا کوئی انتظام نہ ہو سکے جیسا کہ سفر کی حالت ہے تو رہن باقبضہ کی صورت میں قرض دےدو.یوں تو حضر میں بھی رہن رکھنا جائز ہے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قرض لیا اور اپنی زرہ رہن رکھ دی.(مسند احمد بن حنبل مسند عائشۃ ؓ) لیکن سفر کا خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی اور انتظام نہ ہو سکنے کی دقت موجود ہوتی ہے.اس کے بعد نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ.اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے متعلق مطمئن ہو اور اسے بلا رہن روپیہ دے دے تو وہ شخص جسے روپیہ دیا گیا ہے اور جسے امین جانا گیا ہے اس کا فرض ہے کہ دوسرے کے مطالبہ پر روپیہ بلاحجت واپس کر دے.اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے.اس جگہ قرض کو امانت قرار دیا گیا ہے جس میں یہ حکمت ہے کہ دنیا میں عام طور پر امانت کی ادائیگی تو ضروری سمجھی جاتی ہے.لیکن قرض کی ادائیگی میں ناواجب تساہل اور غفلت سے کام لیا جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرض بھی ایک امانت ہی کی قسم ہے.کیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے استعمال کی تم کو اجازت دی جاتی ہے اور تم پر احسان کیا جاتا ہے.تم اس کی ادائیگی میں سستی کرتے ہو.آخر امانت اور قرض میں کیا فرق ہے؟ یہی کہ امانت ایسی حالت میں رکھوائی جاتی ہے جبکہ امین کو ضرورت نہیں ہوتی اور قرض اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ اسے ضرورت ہوتی ہے.ایسی صورت میں قرض لینے والے پر دوسرے کا احسان ہوتا ہے اور اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ وقت پر خندہ پیشانی سے قرض ادا کردے.ضمنی طور پر اس آیت سے ہر قسم کی امانتوں کی حفاظت اور ان کی بروقت واپسی کا بھی ایک عام سبق ملتا ہے جس کی طرف قرآن کریم کی ایک دوسری آیت وَالَّذِیْنَ ھُمْ لِاَمٰنٰتِھِمْ وَ عَھْدِھِمْ رٰعُوْنَ (المومنون: ۹) میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اور نصیحت فرمائی ہے کہ تمدنی معاملات کی ایک اہم شاخ دوسرے کے پاس امانت رکھوانا بھی ہے.پس نہ صرف قرض کے معاملات میں بلکہ امانت کے معاملہ میں بھی تمہیں تقویٰ اللہ سے کام لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ امانت لینے والا آئے اور تم واپسی میں پس وپیش کرنے لگ جائو.پھر ایک اور نصیحت کرتا ہے.فرماتا ہے وَلَاتَکْتُمُوا الشَّھَادَۃَ.تم آپس کے لین دین کے معاملات میں ہمیشہ سچی بات کیا کرو اور کبھی کسی گواہی کو چھپانے کی کوشش نہ کرو.ورنہ تمہارا دل گناہ گار ہو جائے گا.اور جب دل گندہ
Page 530
ہو گیا تو تم میں نورِ ایمان کہاں باقی رہے گا؟ اس آیت میں صرف گواہوں کی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ وہ تمام افراد جو کسی معاملہ میں شریک ہوں ان سب کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا تو الگ رہا سچی گواہی کو بھی چھپانے کی کوشش کرے ورنہ تم دنیوی فائدہ تو ممکن ہے حاصل کرلو لیکن تم سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جائےگی اور تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا.غرض تمدنی مشکلات کے حل کے لئے اسلام نے ان آیات میں نہایت جامع ہدایات دی ہیں.اگر مسلمان ان احکام پر عمل کریں تو وہ کئی قسم کے جھگڑوں اور فسادات سے بچ سکتے ہیں.لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ١ؕ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اور جو کچھ (بھی )آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے.اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ١ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ خواہ تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپائے رکھو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا.پھر جسے چاہے گا بخش دے گا.يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ١ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۰۰۲۸۵ اور جسے چاہے گا عذاب دے گا.اور اللہ ہر ایک چیز پر بڑا قادر ہے.تفسیر.وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُکے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسے لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا والی آیت نے منسوخ کر دیا ہے.یعنی پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اگر تم اسے ظاہرکرویعنی اس کے مطابق عمل کرو تب بھی اور اگر تم اس کو چھپائو یعنی صرف دل کے خیالات تک ہی محدود رکھو تمہارے جوارح اس کے مطابق کوئی عمل نہ کریں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تم سے حساب لے گا.لیکن پھر کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو(کتاب الناسخ و المنسوخ للنحاس باب ذکر الآیۃ التی ھی تتمۃ ثلا ثین اٰیۃ).اور چونکہ دل کے خیالات کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے اس لئے وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ والی آیت منسوخ ہو گئی مگر ان کا یہ خیال درست نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نسخ حالات کے تغیر کے ساتھ تعلق رکھتاہے نہ کہ دل کے خیالات کے ساتھ.مثلاً
Page 531
اسلام میں پہلے گدھے کا گوشت کھانے کی اجازت تھی مگر بعد میں اس سے روک دیا گیا.لیکن صحابہؓ کے دل کی حالت تو پہلے بھی ویسی ہی تھی جیسے بعد میں تھی.یعنی جس طرح پہلے وہ اپنے دل کے خیالات پر کوئی قابو نہیں رکھتے تھے اسی طرح بعد میں بھی نہیں رکھتے تھے.پس دل کے خیالات کے متعلق نسخ کے کوئی معنے ہی نہیں ہیں.منسوخ تو وہ احکام ہوتے ہیں جو تبدیلیٔ حالات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور یہ امر تو تبدیلی پذیر ہے ہی نہیں.اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں.انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیال بھی آجائے اس کے حساب لینے کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے حالانکہ اس آیت میں ان امور کا ذکر ہے جن کو انسان اپنے نفس میں چھپا کر رکھتا ہے.آنی خیالات تو بخشے جائیں گے.لیکن ایک غلط عقیدہ، بغض، حسد اور بخل وغیرہ کے خیالات سب دل میں ہی ہوتے ہیں اگر ان کو بھی بخش دیا جائے تو پھر ایمان کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ پس اس جگہتُخْفُوْهُ سے مراد حسد، کینہ اور بغض وغیرہ ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے.اسی طرح اس سے ایسے خیالات مراد ہیں جن کو انسان اپنے دل میں قائم رکھتا ہے اور جن کو عمل میں لانے کی نیت کر لیتا ہے.لیکن اگر ایک خیال آئے اور انسان اسے اپنے دل سے فوراً نکال دے تو یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک نیکی ہے جس میں اس نے حصہ لیا.پس محض دل کے خیالات قابل مؤاخذہ نہیں جب تک کہ ان پر عمل نہ کیا جائے یا ان کو پختگی سے قائم نہ کر لیا جائے.چنانچہ حضرت ابوہریرہؓ سے صحیحین میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اِنَّ اللّٰہَ تَجَاوَزَ عَنْ اُمَّتِیْ مَاحَدَّثَتْ بِہٖ اَنْفُسُھَا مَالَمْ تَتَکَلَّمْ اَوْ تَعْجَلْ بِہٖ.یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان خیالات سے درگذر فرما دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں.بشرطیکہ وہ ان کو زبان پر نہ لائیں اور نہ ان پر جلدی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں.پس اس آیت میں ان خیالات کا ذکر کیا گیا ہے جن کو انسان اپنے دل میں چھپا کررکھتا ہے اور جن کے متعلق سکیمیں سوچنا شروع کر دیتا ہے.وقتی اور آنی خیالات کا اس میں کوئی ذکر نہیں اور نہ ان پر کوئی گرفت ہے.ہاں غلط عقائد اور بغض اور حسد اور کینہ وغیرہ بھی اگر بغیر توبہ کے بخش دیئے جائیں تو پھر ایمان کی کوئی حقیقت ہی نہیں رہتی اس لئے ان پر مؤاخذہ کیا جائے گا.کیونکہ یہی تمام گناہوں کی جڑھ ہیں.اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ (البقرۃ: ۲۲۶) یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں کرے گا ہاں جو گناہ تمہارے دلوں نے بالارادہ کمایا ہے اس پر تم سے مؤاخذہ کرے گا.دوسری جگہ فرماتا ہے.اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓىِٕكَ كَانَ
Page 532
عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا (بنی اسرائیل: ۳۷) یعنی کان آنکھ اور دل سب کے متعلق انسان سے سوال کیا جائے گا یعنی کان آنکھ کے گناہوں کے علاوہ ان خیالات کا بھی جائزہ لیا جائے گا جو مستقل طور پر کسی انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہے.اسی طرح فرماتا ہے.اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ١ۙ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ١ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (النور:۲۰) یعنی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بدی پھیل جائے.ان کے لئے بڑا دردناک عذاب مقدر ہے.اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.اس آیت میں بھی ان لوگوں کا کوئی عمل بیان نہیں کیا گیا.بلکہ ان کے دل کی حالت بیان کر کے سزا تجویز کی گئی ہے.پس وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں قائم رکھے اور ان کے متعلق سوچتا اور غور کرتا رہے خواہ ان کو عمل میں نہ لا سکے قابل سزا ہیں مگر وہ ناپاک خیالات جو دل میں آئیں اور انسان بائیں طرف تھوک کر اور استغفار اور لاحول پڑھ کر ان کو دل سے نکال دے.ان پر کوئی گرفت نہیں.اسی طرح اوپر کے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ١ؕ وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ.(البقرة: ۲۸۴) یعنی تم سچی گواہی کو مت چھپائو اور یاد رکھو کہ جو شخص سچی گواہی کو چھپاتا ہے وہ یقیناً ایسا ہے جس کا دل گناہ گار ہے.صحیحین میں حضرت ابوہریرہ ؓ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ اِذَا ھَمَّ عَبْدِیْ بِسَیِّئَۃٍ فَلَاتَکْتُبُوْھَا عَلَیْہِ فَاِنْ عَمِلَھَا فَاکْتُبُوْھَا سَیِّئَۃً وَاِذَا ھَمَّ بِحَسَنَۃٍ فَلَمْ یَعْمَلْھَا فَاکْتُبُوْھَا حَسَنَۃً فَاِنْ عَمِلَھَا فَاکْتُبُوْا عَشْرًا (مسلم کتاب الاِیمان باب اذا ھمّ العبد بالحسنة.....) یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ جب میرا بندہ کسی بدی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھو ہاں اگر اس ارادہ کے مطابق عمل بھی کر لے تو ایک بدی اس کے نامہء اعمال میں درج کردو.لیکن اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھو.اور اگر اس نیکی پر عمل کرلے تو پھر دس نیکیاں لکھو.ان آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خیالات تین قسم کے ہیں.اول.ایک وسوسہ یا خیال اٹھا اور خود بخود چلا گیا.اس کا تو نہ ثواب ہے نہ عذاب.دوم.ایک بدعقیدہ دل میں پیدا ہوا یا ایک بدکام کی تحریک دل میںپیدا ہوئی اور اس نے اس کو رد کر دیا.چونکہ بدی کا مقابلہ نیکی ہے اس کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا.سوم.اگر اس نے اس کو باہر نہ نکالا اور اپنا مال سمجھ کر دل میں رکھ لیا.تو اس کو ایک بدی کا گناہ ہو گا.احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی.تو صحابہؓ سخت گھبرائے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم نماز اور روزہ اور جہاد اور صدقہ وغیرہ احکام پر تو
Page 533
عمل کر سکتے ہیں مگر اس آیت میں ایک تو ایسا حکم نازل ہوا ہے جس پر عمل کرنے کی ہم میں طاقت ہی نہیں.اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے فرمایا.اَتُرِیْدُ وْنَ اَنْ تَقُوْلُوْا کَمَا قَالَ اَھْلُ الْکِتٰبِ مِنْ قَبْلِکُمْ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا بَلْ قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَاِلَیْکَ الْمَصِیْرُ فَلَمَّا اقْتَرَأَھَا الْقَوْمُ وَ ذَلَّتْ بِھَا اَلْسِنَتُھُمْ اَنْزَلَ اللّٰہُ فِیْ اَثَرِھَا اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْہِ مِنْ رَّبِّہٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ (مسلم کتاب الاِیمان باب بیان تجاوز اللہ تعالٰی عن حدیث النفس....) یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تم وہی کہو جو اہل کتاب نے تم سے پہلے کہا تھا کہ سَمِعْنَا وَعَصَیْنَا.تمہارا فرض تو یہ ہے کہ تم کہو سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَاِلَیْکَ الْمَصِیْرُ جب صحابہ ؓ نے اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں.اور اس کی مغفرت اور رحم کے طلبگار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اظہار خوشنودی کے طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ارشاد پر صحابہ کرامؓ نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی.پھر یہ آیت منسوخ کس طرح ہو سکتی ہے نسخ تو کسی عمل کا ہوتا ہے اور یہاں کسی عمل کا ذکر نہیں.پس یہ بالکل غلط ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے.اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں تزکیۂ نفس کے لئے خیالات کی پاکیزگی بھی ضروری قرار دی گئی ہے.بے شک خیالات کو کلّی طور پر پاک رکھنا تو ہر انسان کے لئے ناممکن ہے لیکن اگر کوئی بُرا خیال پیدا ہو تو اسے اپنے دل سے نکال دینا تو ہر انسان کے لئے ممکن ہے.مثلاً اگر کسی شخص کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں رشوت لوں تو وہ اس کے متعلق سوچنا اور مختلف قسم کی تدابیر عمل میں لانا شروع نہ کردے بلکہ جہاں تک ہو سکے اس خیال کو فوراً اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرے ورنہ اس کا نقش مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور پھر اس خیال کا مٹانا سخت مشکل ہو جائے گا.اسی طرح اگر کوئی چلتے چلتے کہیں مال دیکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اسے اٹھالوں تو صرف اس خیال کے آنے پر اس سے مؤاخذہ نہیں ہو گا.ہاں اگر اس خیال کے آنے پروہ سوچنا شروع کردے کہ میں کس طرح اس مال کو اٹھائوں اور کس وقت اٹھائوں تو اس کا یہ سوچنا اور تدبیریں کرنا قابل مؤاخذہ ہو گا.غرض وہ خیال جو دل میں گڑ جاتا ہے اور جس کو سوچنے میں انسان لگ جاتا اور تدبیریں شروع کر دیتا ہے اس کا محاسبہ ہو گا.ورنہ اگر کسی کو خیال آئے کہ میں چوری کروں اور وہ اسے فوراً … اپنے دل سے نکال دے تو وہ ایک نیکی کرتا ہے.اسی طرح اگر کسی کو قتل کرنے کا خیال آئے لیکن وہ اسے اپنے دل سے نکال دے تو وہ نیکی کرنے والا سمجھا جائے گا.سزا کا مستحق وہ اسی حالت میں ہوتا ہے جب وہ اس خیال پر قائم رہتا ہے.غرض تزکیۂ نفس کی بنیاد انسانی
Page 534
قلب کی صفائی پر ہے اور اس کی اہمیت رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک اور جگہ بھی بیان فرمائی ہے.آپ فرماتے ہیں.اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضْغَۃً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ کُلُّہٗ وَ اِذَا فَسَدَ تْ فَسَدَ الْجَسَدُ کُلُّہٗ اَ لَا وَھِیَ الْقَلْبُ.(بخاری کتاب الایمان باب فضل من استبرأ لِدینہ) یعنی انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے.جب وہ تندرست ہوتا ہے تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے.پھر آپ نے فرمایا.غور کے ساتھ سنو !کہ وہ گوشت کاٹکڑا دل ہے.پس اسلام میں پاکیزگی اس کا نام نہیں کہ صرف زبان پر اچھی باتیں ہوں یا اعمال تو اچھے ہوں اور دل میں بُرائی ہو.بلکہ اسلام میں اصل پاکیزگی دل کی سمجھی جاتی ہے جو انسان اپنے دل کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہرگز پاک نہیں.ایک شخص اگر قطعاً کوئی گناہ نہ کرے.مگر اس کے دل میں گناہ اور بُرائی سے الفت ہو اور گناہ کے ذکر میں اسے لذّت محسوس ہو تو وہ نیک اور پاک نہیں کہلائے گا.جب تک کہ اس کے دل میں بھی یہ بات نہ ہو کہ اسے گناہوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عادت کے ماتحت انہیں غصہ آجاتا ہے مگر گالی نہیں دیتے لیکن ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلاں انسان بڑا بدمعاش اور شریر ہے ایسے لوگوں کے متعلق ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ پاکیزہ ہیں بلکہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے گند کو چھپائے بیٹھے ہیں.پس اسلام میں پاکیزگی دل کی ہے.اعمال اور زبان تو آلات اور ذرائع ہیں جن سے پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ دل کی حالت بھی محاسبہ کے نیچے آتی ہے.خواہ تم اپنے دل کی حالت کو چھپائو یا ظاہر کرو.یہاں خدا تعالیٰ نے کیا عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے کہ زبان اور اعمال تو دلی حالت کا اظہار کرتے ہیں اصل چیزدل کی حالت ہے اور خدا تعالیٰ اس کا محاسبہ کرے گا.پس فرماتا ہے کہ تم اپنی دلی حالت کو ظاہر کر ویا چھپائو یعنی تم گندے اعمال نہ کرو یا زبان سے ظاہرنہ کرو مگر تمہارے دل میں گند ہے تو ضرور پکڑے جائو گے.یُحَاسِبْکُمْ بِہِ اللّٰہُ میں باء کے تین معنے ہو سکتے ہیں.(۱) ایک معنے ذریعہ اور سبب کے ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تم سے حساب لے گا.یعنی تمہارے اعمال کی بنیاد دل پر رکھی جائے گی.صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ دل کی حالت کو بھی مدّنظر رکھا جائےگا.اور تمہاری نیتوں کو بھی دیکھا جائےگا.جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.(بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی علی رسول اللہ) یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے.پس اعمال کے ساتھ دل کی نیت کو بھی مدّنظر رکھا جائے گا.(۲) دوسرے معنے اس کے فِیْ کے ہو سکتے ہیں یعنی ’’اس کے بارے میں‘‘ جیسا کہ ایک دوسری آیت
Page 535
میں آتا ہے کہ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْۤ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ (البقرۃ: ۲۲۶) (۳) تیسرے معنے اس کے عَلٰی کے ہو سکتے ہیں.یعنی اس جرم پر اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا.يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ میں بتایا کہ جیسی جیسی انسان کی نیت ہو گی ویسی ہی اس کی جزا ہو گی.سزا کے مستحق سزا پائیں گے اور جو مغفرت کے مستحق ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دامن مغفرت میں لے لےگا.سورۂ بقرہ کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کے چار عظیم الشان کاموں کا ذکر کیا گیا تھا.اوّل.تلاوتِ آیات.دوم تعلیم کتاب.سوم تعلیم حکمت.چہارمؔ.تزکیہ نفوس.آپؐ کے ابتدائی تین کاموں پر اس سورۃ میں تفصیلاً روشنی ڈالی گئی ہے.اب صرف یُزَکِّیْھِمْ کے وعدہ کا ایفاء باقی تھا.سو اس رکوع میں اس شق پر بھی روشنی ڈال دی.ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ تزکیہ نفوس کا کام کسی انسان کے بس کا نہیں.آخر والدین سے زیادہ محبت کرنےوالا اور کون وجود ہو سکتا ہے مگر وہ بھی اپنی اولاد کا تزکیہ نفس نہیں کر سکتے.تزکیہ میں دوباتیں ضروری ہوتی ہیں.اول ترک گناہ.دومؔ روحانیت میں ترقی.ترکِ گناہ کے لحاظ سے فرمایا کہ ہم تم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہرچیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور آسمان و زمین اور کائنات کا ذرہ ذرہ سب اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے.پس جس چیز کے لینے کی وہ اجازت دے صرف وہی تم لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جائو کیونکہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی چیز کو استعمال کرنے والا مستوجب سزا قرار پاتا ہے.دوسری شق روحانیت میں ترقی کرنا تھا.اس کے لئے فرمایا کہ سب کچھ ہمارا ہے.اور ہمارے ہی ذریعہ سے ہر قسم کی خیروبرکت مل سکتی ہے.اس لئے جب تم ہمارے حکموں کی اطاعت کروگے تو ہم تم کو اپنی مغفرت کے دامن میں لے لیں گے.اور ہمارا قادرانہ تصّرف تمہیں ہمارے قرب میں پہنچا دے گا.اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ١ؕ جو کچھ بھی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس پر وہ(خود بھی) ایمان رکھتا ہے اور (دوسرے) كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ١۫ لَا نُفَرِّقُ مومن بھی( ایمان رکھتے ہیں).یہ سب (کے سب) اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں
Page 536
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ١۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا١ٞۗ پر ایمان رکھتے ہیں.(اور کہتے ہیں کہ) ہم اس کے رسولوں میں ایک (دوسرے )کے درمیان (کوئی )فرق نہیں غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۰۰۲۸۶ کرتےاور (یہ بھی) کہتے ہیں کہ ہم نے (اللہ کا حکم) سن لیا ہے اور ہم اس کے (دل سے )فرمانبردار ہو چکے ہیں.(یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ )اے ہمارے رب !ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے.تفسیر.اس آیت میں تزکیۂ نفوس کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ پر ،اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا مومن کا شعار قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب تک عقیدہ اور عمل دونوں کی اصلاح نہ ہو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا.مگر افسوس ہے کہ اتنی واضح آیت کے باوجود بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نجات کے لئے صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آنا کافی ہے.اس کے رسولوں اور کتابوں وغیرہ پر ایمان لانا ضروری نہیں.اسی قسم کے خیالات ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کے بھی تھے(حقیقة الوحی روحانی خزائن جلد ۲۲ صفحہ۱۱۲).اور انہی خیالات کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ و السلام نے اسے اخراج از جماعت کی سزادی اور بڑے زور سے تحریر فرمایا کہ یہ عقیدہ اسلام کے سراسر خلاف ہے.اسلام تمام رسولوں پر اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لانا نجات کے لئے ضروری قرار دیتا ہے.لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کسی ایک رسول کا انکار بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنا دیتا ہے.پس خواہ کوئی نبی تشریعی ہو یا غیرتشریعی پہلے زمانہ میں آچکا ہو یا آئندہ زمانہ میں آئے ہر ایک کا ماننا ضروری ہے.بیشک مدارج کے لحاظ سے ان میں بڑا فرق ہے.جس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں اس مقام پر نہ موسیٰ علیہ السلام ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام اور نہ کوئی اور نبی.مگر جہاں تک نفس ِ ایمان کا سوال ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح بغیر کسی فرق کے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اس لحاظ سے انبیاء میں کسی قسم کی تفریق پیدا کرنا جائز نہیں.اسی طرح خدائی کلام پر عمل کرنے کے لحاظ سے بھی انبیاء میں کسی قسم کا کوئی امتیاز کرنا جائز نہیں.بیشک ان کے درجات مختلف ہوں لیکن ان پر کلام نازل کرنے والا چونکہ ایک ہی ہے اس لئے یہ فرق کرنا کسی صورت میں بھی
Page 537
جائز نہیں کہ مثلاً فلاں نبی چونکہ درجہ میں بڑا ہے اس لئے اس پر نازل ہونے والے کلام کو تو ہم مانیں گے لیکن فلاں نبی چونکہ درجہ میں چھوٹا ہے اس لئے اس پر نازل ہونے والے کلام کو ماننا ہمارے لئے ضروری نہیں.اس قسم کا احمقانہ فرق کرنا ایسا ہی ہے جیسے مثلاً کوئی کہے کہ میرے افسر نے فلاں حکم چونکہ رجسٹری کے ذریعہ نہیں بھیجا بلکہ عام ڈاک میں بھیجا ہے اس لئے میں نے اس کی تعمیل نہیں کی.کیا جاہل سے جاہل شخص بھی اس قسم کا عذر پیش کر سکتا ہے اور کیا اسے تسلیم کرنے کے لئے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر خدائی کلام کے متعلق یہ فرق کس طرح کیا جا سکتا ہے.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی مومنوں کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْکَ الْمَصِیْرُ یعنی وہ احکامِ الٰہیہ کی اطاعت میں ایک ذراسی غفلت اور سستی بھی گوارا نہیں کرتے بلکہ ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا.اے ہمارے رب! ہم نے تیرا حکم سن لیا اور ہم اس کے دل سے فرمانبردار ہیں.غُفْرَانَکَ رَبَّنَا وَ اِلَیْکَ الْمَصِیْرُ.غُفْرَانَكَ دراصل اِغْفِرْ غُفْرَانَكَ ہے.یعنی غُفْرَانَكَ سے پہلے ایک فعل محذوف ہےاور معنے اس کے یہ ہیں کہ اے ہمارے ربّ! ہمیں اپنی بخشش سے حصہ دے اور ہمیں معاف فرما.چونکہ گذشتہ آیات میں تزکیۂ نفس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی تھی.اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ کے نتیجہ میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَیْکَ الْمَصِیْرُ کہنے والی ہے اور جس کا سر خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر حالت میں جھکا رہتا ہے.لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا١ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا اللہ کسی شخص پر سوائے اس (ذمہ داری) کے جو اس کی طاقت میں ہو کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا.جو اس نے (اچھا) کام کیا مَا اكْتَسَبَتْ١ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا١ۚ ہو( وہ بھی) اس کے لئے( نفع مند) ہو گا اورجو اس نے (برا) کام کیا ہو (وہ بھی) اسی پر (وبال ہو کر) پڑے گا.(اور وہ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ یہ بھی کہتے ہیں کہ) اے ہمارے ربّ! اگر (کبھی) ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں سزا نہ دیجیئو.اے
Page 538
مِنْ قَبْلِنَا١ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ١ۚ ہمارے رب! اور تو ہم پر( اس طرح) ذمہ داری نہ ڈال جس طرح تو نے ان لوگوں پرجو ہم سے پہلے (گزر چکے) وَاعْفُ عَنَّا١ٙ وَ اغْفِرْ لَنَا١ٙ وَ ارْحَمْنَا١ٙ اَنْتَ مَوْلٰىنَا ہیں ڈالی تھی اے ہمارے رب! اور اسی طرح ہم سے (وہ بوجھ )نہ اٹھوا جس (کے اٹھانے) کی ہمیں طاقت نہیں.اور فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ� ہم سے درگزر کر اورہمیں بخش دے.اور ہم پر رحم کر (کیونکہ) تو ہمارا آقا ہے پس کافروں کے گروہ کے خلاف ہماری مدد کر.حلّ لُغات.یُکَلِّفُ کَلَّفَہٗ کے معنے ہیں اَمَرَہٗ بِمَایَشُّقُّ عَلَیْہِ اسے ایسے کام کا حکم دیا جو اس پر گراں گذرا.حدیث میں آتا ہے کُلِّفْنَا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا نُطِیْقُ ( مسلم کتاب الایمان باب قولہ تعالٰی و ان تبدوا ما فی اَنفسکم) ہمیں ایسے ہی اعمال کا حکم دیا گیاہے جن کی بجا آوری کی ہم طاقت رکھتے ہیں.اِصْرًا اَلْاِصْرُ کے معنے ہیں اَلثِّقْلُ.بوجھ اَلْعَھْدُ.پختہ عہد.اَلذَّنْبُ.گناہ.(اقرب) حَمَّلْتَہٗ حَمَّلَہُ الْاَمْرَ کے معنے ہیں جَعَلَہٗ یَحْمِلُہٗ وَ کَلَّفَہٗ بِحَمْلِہٖ.اس سے بوجھ اٹھوایا اور بوجھ اٹھوا کر اسے تکلیف اور مشقّت میں ڈالا.تفسیر.لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس کی بجاآوری کی انسان میں طاقت نہ ہو.یا اس کی استعداد اور قابلیت سے بالا ہو.پس جبکہ اس کی طرف سے ہمیشہ ایسے ہی احکام نازل ہوتے ہیں جن پر عمل انسانی مقدرت سے باہر نہیں ہوتا تو لازماً سب ذمہ داری انسان پر ہی عائد ہوتی ہے اور انعاماتِ الٰہیہ کا بھی وہی مستحق ٹھہرتا ہے اور عدمِ تعمیل کی بنا پر سزا کا بھی وہی مستحق قرار پاتا ہے اسی لئے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ لَھَا مَاکَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اکْتَسَبَتْ.یعنی انسان اگر اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ بھی اسے ہی پہنچے گا.اور اگر بُرا کام کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسے ہی ہو گا.ضمناً اس آیت میں اس مضمون کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جو کام اس زمانہ میں امتِ محمدیہ کے سپرد ہوا
Page 539
ہے وہ اس کی طاقت اور قابلیت کے عین مطابق ہے اور ایک دن وہ اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچا کر دنیا کو دکھا دے گی کہ وہ اس منصب کی سب سے زیادہ اہل تھی.اگر یہی کام پہلے کسی نبی کی امت کو کرنا پڑتا تو وہ اسے کبھی سرانجام نہ دے سکتی.(۲) اس آیت میں اسلام کی اس فضیلت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے تمام احکام میں انسان کی کمزوریوں اور ضروریات کو مدّنظر رکھتے ہوئے ایسی لچک رکھی گئی ہے کہ ہر حالت میں وہ ان پر عمل کر سکتا ہے.مگر باقی مذاہب اپنی تعلیم میں یا تو افراط کی طرف چلے گئے ہیں یا تفریط کی طرف اور اس طرح وہ اپنے حقیقی توازن کو کھوبیٹھے ہیں.اور قلوب پر ان کی حکومت جاتی رہی ہے.صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو فطرت انسانی کے مطابق تعلیم دینے کی وجہ سے انسان کے دل پر حکمرانی کر رہا ہے.(۳) اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جب تم کو تمام احکام تمہاری طاقت اور قابلیت کے مطابق دیئے گئے ہیں اور تم پر کوئی ناقابلِ برداشت بوجھ نہیں ڈالا گیا تو اب تمہارا فرض ہے کہ تم بھی دیانتداری کے ساتھ ان احکام پر ایسا عمل کرو جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے.(۴) اس آیت میں کفارہ کا بھی ردّ کیا گیا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنا انسانی مقدرت سے بالا نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر ایسی طاقت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر گناہوں پر غالب آنا چاہے تو آسکتا ہے.پس اس کی نجات کے لئے کسی کفارہ کی ضرورت نہیں بلکہ انسان کو خود اپنے فطری قویٰ کو ابھارنے اور ان سے کام لینے کی ضرورت ہے.لَھَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْھَا مَا اکْتَسَبَتْ میں بتایا کہ ہم نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا فائدہ پہنچے گا اور اگر کوئی بُرا کام کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسے ہی پہنچے گا.کسب اور اکتساب میں یہ فرق ہے کہ کسب کی نسبت اکتساب میں زیادہ محنت اور مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے پس نیکی کے متعلق کسب اور بدی کے متعلق اکتساب کا لفظ رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نیکی ایک فطری چیز ہے جس پر عمل انسان کے لئے کوئی بوجھ نہیں ہوتا لیکن بدی ایک غیرفطری چیز ہے جو اخلاقی قوتوں کو برمحل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کے مرتکب کو ایسے رستہ پر چلنا پڑتا ہے جو اس کے لئے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتا ہے.پھر ان الفاظ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نیکی تو ہر حال میں قابلِ جزا ہے.لیکن بدیوں میں سے
Page 540
صرف اس بدی کی سزا ملے گی جس میں اکتساب کا رنگ پایا جائے گا.یعنی قصداً اور ارادتاً اس کا ارتکاب کیا جائے گا.اس کے بعد تزکیہ نفس کے لئے اللہ تعالیٰ مومنوں کو بعض خاص دعائیں سکھلاتا ہے کیونکہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھتا ہے اور دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اس کی قدرتوں پر زندہ ایمان پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دُعا جو اللہ تعالیٰ خود سکھائے اس کی قبولیت میں تو کسی شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے مومن بندے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا.اے ہمارے ربّ! اگر ہم کبھی بھول جائیں یا کوئی خطا ہم سے سرزد ہو جائے تو ہمیں سزا نہ دیجیئو بلکہ ہم سے رحم اور عفو کا سلوک کیجیئو.بھول جانے کے معنے یہ ہیں کہ کوئی کام کرنا ضروری ہو مگر نہ کیا جائے اور خطا کے یہ معنے ہیں کہ کام تو کیا جائے مگر غلط کیا جائے.بعض لوگ اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ نسیان اور خطا دو ہم معنے لفظ یہاں کیوں لائے گئے ہیں.وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں تمام کام دو قسم کے ہوتے ہیں کوئی کام تو ایسے ہوتے ہیں جو کرنے ضروری ہوتے ہیں مگر انسان نہیں کرتا اور کوئی کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا تو ہے مگر غلط طور پر کرتا ہے اور یہ دونوں ہی غلطیاںہوتی ہیں.نسیان کے معنے بھول جانے کے ہیں اور بھولنا کرنے کے متعلق ہوتا ہے نہ کرنے کے متعلق نہیں ہوتا.پس لَا تُؤَاخِذْنَااِنْ نَّسِيْنَاۤ کے معنے یہ ہوئے کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ جو کام ہمارے لئے کرنے ضروری ہیں وہ ہم نہ کریں اور اس طرح ہم ترقی سے محروم ہو جائیں.پس تو ہماری حفاظت فرمااور ہمیں اس غلطی سے محفوظ رکھ.اَوْ اَخْطَاْنَا ا ور یا الٰہی یہ بھی نہ ہو کہ جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کر لیں یا ہم کریں تو وہی جو ہمیں کرنا چاہیے مگر غلط طریق پر کریں پس نسیان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام کرنے تھے وہ انسان سے رہ جائیں اور خطا کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر لئے جائیں یا جن کاموں کا کرنا ضروری تھا وہ غلط طور پر کئے جائیں.غرض نسیان عدم عمل کا نام ہے اور خطا عمل کی خرابی کو کہتے ہیں.اسی لئے یہاں دو لفظ استعمال کئے گئے ہیں.پس ان میں سے کوئی لفظ بھی زائد نہیں بلکہ ہر لفظ اپنی اپنی جگہ ضروری ہے.نسیان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آدمؑ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَہٗ عَزْمًا (طٰہٰ : ۱۱۶) یعنی آدم ؑ بھول گیا لیکن ہم نے بھی دیکھ لیا کہ اس کے دل میں ہمارا حکم توڑنے کے متعلق کوئی ارادہ نہ تھا.پھر فرماتا ہے.رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا.یعنی مومن یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا!ہم پر اس طرح ذمہ واری نہ ڈالیو.جس طرح تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں ڈالی تھی.اِصْـرٌ کے ایک معنے چونکہ گناہ کے ہیں اس لئے اس دعا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اے خدا! تو ہم پر اس
Page 541
طرح گناہ نہ ڈال جس طرح تو نے پہلی قوموں پر ڈالا.یعنی ہمیں ان اعمال سے اپنے فضل سے محفوظ رکھ جن کے نتیجہ میں ہماری طرف گناہ منسوب ہوں.اور دنیا میں ہمیں ظالم اور روسیاہ قرار دیا جائے اور طرح طرح کے عیوب ہماری طرف منسوب کئے جائیں جیسا کہ پہلی قوموں کے ساتھ ہوا.اِصْـرٌ کے دوسرے معنے عھدٌ کے ہیں اس لحاظ سے لَاتَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا کے معنے یہ ہیں کہ الٰہی! ہم سے کوئی ایسا عہد نہ لیجیئو جس کو توڑ کر ہم تیری سزا کے مستوجب ہوں جس طرح پہلی قومیں سزا کی مستوجب ہوئیں.یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عہد لینا بُری چیز تھی تو پھر دوسری امتوں سے کیوں لئے گئےاور اگر اچھی چیز ہے تو اس امت سے کیوں نہ لیا جائے؟ بلکہ اس کے کامل اُمت ہونے کی وجہ سے تو ضروری ہے کہ اس کے ہر فرد سے عہد لیا جائے.سویاد رکھنا چاہیے کہ لَاتَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم سے کوئی عہد ہی نہ لیا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے ربّ! آپ ہم سے جو عہد لیں اس کے متعلق ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں اور پہلی قوموں کی طرح عہد شکن اور غدار قرار نہ پائیں.گویا یہ دعا عہد سے بچنے کے لئے نہیں بلکہ عہد کی ذمہ داریوں پر باحسن طریق عمل پیرا ہونے کے لئے ہے.(۳)اِصْرٌ کے ایک معنے بوجھ کے بھی ہیں.اس لحاظ سے اس کے معنے یہ ہیں کہ اے ہمارے ربّ! تو ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا.اس کے یہ معنے نہیں کہ ہمیں اتنی نمازیں پڑھنے کو نہ بتا کہ جو ہم پڑھ نہ سکیں کیونکہ خدا تعالیٰ پہلے ہی فرماچکا ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتے ہیں وہ انسان کی طاقت اور اس کی توفیق کے مطابق ہوتے ہیں.پس اس کے یہ معنے نہیں بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ بعض جرائم کی بنا پر پہلے لوگوں کے لئے جو سزائیں نازل کی گئی تھیں وہ سزائیں ہم پر نازل نہ ہوں اور ہم سے وہ غلطیاں سرزد نہ ہوں جو پہلے لوگوں سے سرزد ہوئیں اور جن کی وجہ سے وہ تباہ کر دیئے گئے.انہوں نے تیری نافرمانیاں کیں اور تیرے احکام کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا جس کی وجہ سے ان پر ایسی حکومتیں مسلّط ہوئیں اور ایسے قوانین ان کے لئے مقرر کر دیئے گئے جو ان کے لئے ناقابلِ برداشت تھے.تو ہمیں اپنے فضل سے ایسے مقام پر کھڑا کیجیئوکہ ہم سے ایسی خطائیں سرزد نہ ہوں اور ہمیں ایسی سزائیں نہ ملیں جو ہمارے نفس کی طاقت برداشت سے باہرہوں اس کے یہ معنے نہیں کہ نفس کی طاقتِ برداشت کے مطابق اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا ملے تو اس میں کوئی حرج نہیں.اصل بات یہ ہے کہ ہر روحانی سزا انسان کی برداشت سے باہر ہوتی ہے.یہ انسان کی رذالت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی سزا کو برداشت کر لیتا ہے ورنہ اگر شرافتِ نفس ہو تو چھوٹی سے چھوٹی سزا
Page 542
بھی انسان کے لئے ناقابلِ برداشت ہوتی ہے.چنانچہ دیکھ لو.جب کسی کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو اس کی معمولی سی ناراضگی کو دیکھ کر ہی اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے.بعض دفعہ کہتا ہے.اس نے اپنی آنکھیں میری طرف نہیں پھیریں.بعض دفعہ کہتا ہے اس نے مجھ سے اچھی طرح باتیں نہیں کیں.بعض دفعہ کہتا ہے اس نے مجھ سے باتیں تو کیں مگر ان میں بشاشت معلوم نہیں ہوتی تھی اور اس بات کا اس کی طبیعت پر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ وہ غمگین ہو جاتا ہے.پس اس سے یہ مراد نہیں کہ ہمیں بڑی سزا نہ دیجیئو چھوٹی سزا دیجیئو بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی سزا دیجیئو ہی نہیں نہ چھوٹی نہ بڑی.پھر دنیا میں بعض مصائب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر قصور کے آجاتے ہیں.قصور ہمسایہ کا ہوتا ہے اور دکھ اسے پہنچ جاتا ہے قصور دوست کا ہوتا ہے اور سزا کا اثر اس پر آپڑتا ہے اس لئے جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ دعا سکھلائی کہ تم یہ کہا کرو کہ ہم سے ایسی خطا یا نسیان نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہم تیری سزا کے مستحق ہو جائیں.وہاں دوسری دعا یہ سکھلائی کہ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ.اے خدا! ایسا نہ ہو کہ قصور تو ہمارے ہمسایہ کا ہو اور سزا ہمیں مل جائے.یا قصور دنیا کا ہو اور اس کی مصیبت کا اثر ہم پر آپڑے مگر یہاں ایک شرط بڑھا دی اور وہ یہ ہے کہ مَالَاطَاقَۃَ لَنَا بِہٖ اس شرط کو اس لئے بڑھایا گیا ہے کہ یہاں ناراضگی کا سوال نہیں بلکہ دنیوی مصائب اور ابتلائوں کا ذکر ہے ناراضگی بے شک چھوٹی بھی برداشت نہیں ہو سکتی مگر چھوٹی تکلیف برداشت کر لی جاتی ہے.پس جہاں روحانی سزا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر تھا وہاں تو یہ دعا سکھلائی کہ ہم میں تیری کسی ناراضگی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں وہ ناراضگی چھوٹی ہو یا بڑی مگر جب دنیوی تکالیف کا ذکر آیا تو یہ دعا سکھلائی کہ چھوٹے موٹے ابتلائوں پر مجھے اعتراض نہیں.میں یہ نہیں کہتا کہ میرا قدم ہمیشہ پھولوں کی سیج پر رہے.البتہ وہ ابتلا ء جو تیری ناراضگی کا موجب نہیں اور جو دنیا میں عام طور پر آیا ہی کرتے ہیں.ان کے متعلق میری صرف اتنی درخواست ہے کہ کوئی ابتلاء ایسا نہ ہو جو میری طاقت سے بالا ہو.یہ مطلب نہیں کہ مومن ایسے ابتلاء خودچاہتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے چونکہ بتایا ہوا ہے کہ میں مومنوں کا امتحان لیا کرتا ہوں اس لئے مومن یہ نہیں کہتا کہ خدایا میرا امتحان نہ لے بلکہ وہ کہتا ہے خدایا امتحان تو لیجیئو مگر ایسا نہ لیجیئو کہ میری طاقت سے بڑھ کر ہو.غرض جو حصہ ناراضگی کا تھا وہاں تو کہہ دیا کہ میں ذراسی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتا.مگر جہاں دنیوی تکالیف اور ابتلائوں کا ذکر تھا وہاں کہہ دیا کہ خدایا! تکالیف تو آئیں مگر ایسی نہ ہوں جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہوں.
Page 543
پھر فرمایا وَاعْفُ عَنَّا.اے خدا ہم سے عفو کر.یہ نَسِيْنَآکے مقابلہ میں ہے.یعنی جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے چونکہ ہم نے نہیں کئے اس لئے ہمیں تو معاف فرمادے.وَاغْفِرْلَنَا اور جو غلط کام ہم کر چکے ہیں ان کے خمیازہ سے ہمیں بچا لے اور ان کاموں کو نہ کئے کی طرح کر دے.عفو کے معنے رحم کے بھی ہوتے ہیں اور جو چیز کسی انسان سے رہ جائے اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ مہیّا کر دی جائے.اس لئے وَاعْفُ عَنَّا کے یہ بھی معنے ہیں کہ جو چیز رہ گئی ہے اس کو تو اپنے فضل اور رحم سے ہمیں مہیّا فرمادے.اس کے مقابلہ میں جو کام غلط ہو جائے اس کی درستی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے.چنانچہ اَخْطَاْنَا کے مقابلہ میں اغْفِرْ لَنَا رکھ دیا.اور غَفَرَ کے معنے عربی زبان میں مٹا دینے کے ہی ہوتے ہیں (مفردات).پس اس کے معنے یہ ہیں کہ اے خدا جو کام ہم غلط طور پر کر چکے ہیں ان کو مٹادے اور انہیں نہ کئے کی طرح کردے.گویا ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ جو کام ہم نے نہیں کیا اور اس طرح رخنہ واقع ہو گیا ہے اس رخنہ کو تو اپنے فضل سے پُر کر دے اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ جو کام ہم غلط طور پر کر چکے ہیں ان کو تو مٹا ڈال.وَارْحَمْنَا پھر اس کام کے نتیجہ میں ہم سے جو اور غلطیاں ہوئی ہیں اور جن ترقیات کے حصول میں روک واقع ہو گئی ہے ان غلطیوں کے متعلق بھی ہم پر رحم فرما.اور ہماری ترقیات کے راستہ میں جو روکیں حائل ہو گئی ہیں ان کو اپنے فضل سے دُور کر دے.اَنْتَ مَوْلٰىنَا تو ہمارا مولیٰ ہمارا آقا اور ہمارا مالک ہے.آخر ہماری کمزوریاں کسی نہ کسی رنگ میں لوگوں نے تیری طرف ہی منسوب کرنی ہیں.لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ خدائی جماعت کہلاتی تھی مگر اسے بھی دکھ پہنچا اور اسے بھی دوسروں کی طرح تکلیف ہوئی.پس اے ہمارے مولیٰ! تو ہمارا آقا ہے اور ہم تیرے خادم.تو آقا ہونے کے لحاظ سے ہم پر رحم کر کیونکہ ہماری کمزوریاں آخر تیری طرف ہی منسوب ہوں گی اور لوگ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے.احادیث میں آتا ہے کہ غزوۂ اُحد میں جب ابوسفیانؔ نے بڑے زور سے کہا کہ لَنَا عُزّٰی وَلَاعُزّٰی لَکُمْ یعنی ہماری تائید میں ہمارا عزّٰی بُت ہے.مگر تمہاری تائید میں کوئی بت نہیں.تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم کہو.لَنَا مَوْلٰی وَلَامَوْلٰی لَکُمْ.(بخاری کتاب المغازی باب غزوة اُحد) ہمارا والی اور ہمارا مددگار ہمارا حیّ و قیوم خدا ہے مگر تمہارا کوئی والی اور مددگار نہیں.یہ اَنْتَ مَوْلٰىنَا کی سچائی کا کیسا عملی ثبوت تھا کہ تلواروں کے سایہ میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ اللہ ہمیں بچا سکتا ہے.
Page 544
آخرمیں یہ تعلیم دی کہ تم خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہو کہفَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ یعنی اے خدا ! ہمیں کافروں کی قوم پرغلبہ عطا فرما.ہم بے بس اور کمزور ہیں لیکن ہمارا دشمن طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہے.ہمارا غلبہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ تو ہمارے ساتھ ہو اور اپنے رحم اور کرم سے کام لےکر ہمارے ایک ایک آدمی کے اندر ایسی روح پھونک دے کہ وہ سوسو بلکہ ہزار ہزار مخالف پر بھی بھاری ہو اگر تو اپنے فضل سے ایسے سامان پیدا فرماوے تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ ہمارے بچائو کی اور کوئی صورت نہیں.پس اے ہمارے رب! جو لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جن سے اسلام کی ترقی میں روک واقع ہوتی ہے ان پر تو ہمیں غالب کر اور ایسے سامان پیدا فرما جو تیری تبلیغ اور تیرے نام کو دنیا میں پھیلانے کا باعث ہوں.پھر یہ دُعا صرف مادی غلبہ کے لئے ہی نہیں بلکہ روحانی رنگ میں بھی دشمنوں پر غالب آنے کے لئے ایک عاجزانہ پکار ہے اور اس میں خدا تعالیٰ کے حضور یہ عرض داشت پیش کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب! اگر ہمارے اندر تیرے اس پاک رسول پر ایمان لانے کے نتیجہ میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا اور کفار میں اور ہم میں ایک نمایاں روحانی امتیاز اور فرق لوگوں کو محسوس نہ ہوا.ہمارے اخلاق اور کردار ان سے بلند نہ ہوئے اور ہمارے معاملات ان سے بہتر نہ ہوئے تو دنیا ہمیں طعنہ دے گی کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کیا فائدہ اٹھایا؟ ان میں تو کوئی بھی تبدیلی پیدا نہ ہوئی.پس اے خدا! تو اپنے فضل سے ہمیں اپنے اندر ایسا نیک تغیر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے رحم اور کرم کو جذب کر لیں اور کفار پر ہمیں جسمانی رنگ میں ہی نہیں بلکہ اخلاق اور روحانیت کے لحاظ سے بھی ایک نمایاں تفوق اور غلبہ حاصل ہو جائے اور تیرا دین دنیا کے کناروں تک پھیل جائے.تـــــــــــــــــــــمّــــــــــــــــــت وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
Page 545
اگرظاہری الفاظ کا ہی اتباع کیا جائے تو مفسرین کے بیان کردہ معنے یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے معنے یہ بنتے ہیں کہ’’تیرا آسمان میں اِدھر اُدھر اپنا منہ پھیرنا‘‘.اور یہ خود ایک ناقابلِ تسلیم بات ہے.کیونکہ منہ کا آسمان میں تقلب کرنا ناممکن ہے پس الفاظ قرآنی ان معنوں کو برداشت نہیں کرتے.اصل بات یہ ہے کہ فِیْ کے معنے اس جگہ اِلٰی کے ہیں.اور اس کی مثال قرآن کریم میں بھی موجود ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جَآءَ تْھُمْ رُسُلُھُمْ بِالبَیِّنٰتِ فَرُدُّ وْا اَیْدِیَھُمْ فِیْ اَفْوَاھِھِمْ( ابراہیم :۱۰) یعنی جب لوگوں کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے ہاتھ ان کے مونہوں کی طرف لوٹا دیئے.اس جگہ فِیْ اَفْوَاھِھِمْ سے ان کے مونہوں میں ہاتھ ڈالنا مراد نہیں بلکہ ان کی طرف لوٹانا مرا د ہے.اسی طرح یہاں تَقَلُّبَ وَجْھِکَ فِی السَّمَآءِ سے آسمان میں اِدھر اُدھر منہ پھیرنا مرادنہیں بلکہ آسمان کی طرف آپ کی توجہ کا بار بار پھرنا مراد ہے ورنہ آسمان کی طرف مونہہ اُٹھاناتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار کے بھی خلاف تھا.میرے نزدیک اس کے یہی معنے ہیں کہ ہم تیری توجہ کے بار بار آسمان کی طرف جانے کو دیکھ رہے ہیں.اور یہ ایسا ہی فقرہ ہے جیسے ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ ہماری نظر تو فلاں طرف لگی ہوئی ہے.یعنی ہمیں وہاں سے کامیابی کی اُمید ہے اسی طرح گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ملا تھا.مگر پُرانی پیشگوئیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اُس وقت تک ظاہر کی تھیں اور دوسرے کلام سے آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ آخر قبلہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ملے گا اور وہ ترقی کا پہلا زینہ ہو گا.کیونکہ اسلام کی ترقیات کے زمانہ کا اس امر کو نشان قرار دیا گیا تھا.پس آپ بار بار خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے تھے کہ کب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ملتا ہے.یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فِیْ اپنے اصلی معنوں میں ہو اور سماء سے مراد احکامِ سماوی ہوں اور معنے یہ ہوں کہ تیری توجہ کا آسمانی احکام کے متعلق تقلّب یعنی تیری توجہ آسمانی احکام کے متعلق تقلّب کر رہی تھی اور بے قرار تھی کہ وہ کب نازل ہوتے ہیں.عربی زبان کا محاورہ بھی ہے کہ تَکَلَّمْتُ مَعَکَ فِیْ فُلَانٍ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں شخص کے بارے میں کلام کیا.اس لحاظ سے قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ کے یہ معنے ہوںگے کہ ہم آسمانی احکام کے بارے میں تیری توجہ کا تقلّب دیکھ رہے ہیں.یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ خدائی حکم نازل ہو اور آئندہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے.فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تجھے اس قبلہ کی طرف پھیر دیںگے جسے تو پسند کرتا ہے.یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ کے وہی معنے صحیح ہیں جو میں نے کئے ہیں.کیونکہ اگر اس سے پہلے
Page 547
کی طرف پھیر دو.پہلی جگہ واحد مخاطب کا صیغہ رکھا اور دوسری جگہ جمع کا.اسی طرح پہلے وَجْھَکَ فرمایا اور پھر وُجُوْھَکُمْ فرمایا.اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے فقرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے اور دوسرے فقرہ میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے جو مختلف بلاد وامصار میں رہتے تھے بیشک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ بھی بیت اللہ کی طرف ہی منہ کرتے تھے.مگر آپ کا زیادہ ترقیام مدینہ میں ہی تھا.اور باہر کا قیام عارضی تھا.لیکن دوسرے لوگوں کا مدینہ کا قیام عارضی تھا اور باہر کا مستقل اس لئے پہلی جگہ صرف آپ کو مخاطب کیا گیا.اور چونکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں نے بھی اُدھر ہی منہ کرنا تھا جدھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تھا اس لئے ان کا علیٰحدہ ذکر نہ کیا گیا.اور آپ کی نماز میں ہی ان کی نماز کو شامل کر لیا گیا.میں سمجھتا ہوں اس آیت سے یقینی طور پر یہ استدلال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں نماز باجماعت کو نہایت ضروری قرار دیا ہے.کیونکہ اس نے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرمایا ہے.فَوَلُّوْا وُجُوْھَکُم شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَــرَامِنہیں فرمایا.اور اس کی وجہ یہی ہے کہ باقی سارے مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقتدائے نماز میں شامل ہونا تھا سوائے منافقوں کے جو دل سے ساتھ نہیں ہوتے اور عمل میں بھی پیچھے رہتے ہیں اور جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو عشاء اور فجر کی نمازوں میں نہیں آتے.میرا جی چاہتا ہے کہ میں اُن کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دوں(صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلٰوة باب فضل صلوۃ الجماعۃ...).پس چونکہ تمام مومنوں نے نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ساتھ ہی شریک ہوجانا تھا اس لئے اُن کا علیحٰدہ ذکر کرنے کی بجائے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا کہ آپ اپنا منہ مسجدحرام کی طرف پھیر لیں.بہرحال نماز باجماعت اسلام کا ایک نہایت ہی اہم حکم ہے.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اس کے متعلق اس قدر تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک نابینا شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں اور راستہ میں لوگ پتھر وغیرہ ڈال دیتے ہیں جن سے مجھے ٹھوکر یں لگتی ہیں.کیا میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں؟ پُرانے زمانہ میں لوگ دیواروں کے ساتھ ساتھ پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ مکان بارش کے پانی سے محفوظ رہیں اور دیواریں خراب نہ ہوں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اجازت تو دے دی لیکن پھر فرمایا.کیا تمہارے مکان تک اذان کی آواز آتی ہے؟ اس نے کہا یارسول اللہ آتی ہے.آپ نے فرمایا.پھر جس طرح بھی ہو مسجد میں آیا کرو(صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلٰوة باب یجب ایتان المسجد ).مگر آجکل
Page 556
کہ وہ غیروں کے متعلق بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ آپؐ کو نام لے کر پکاریں ان کے متعلق یہ تصور بھی کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود آ پؐ کو محمد ؐ کہہ کر پکارتے ہوں.پس اس روایت کے یہ الفاظ کہ محمدؐ پہلے صخرئہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتا تھا جو یہود کا قبلہ تھا اور سترہ ماہ تک وہ ایسا ہی کرتا رہا اور اس نے بیت المقدس کی طرف منہ اس لئے کیا تھا کہ وہ یہود کو خوش کرے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور اس کی اتباع کریں.لیکن جب وہ اس ذریعہ سے مسلمان نہ ہوئے تو پھر اس نے مکہ کی طرف منہ کر لیا خود اپنی ذات میں اس امر کا ثبوت ہیں کہ یہ الفاظ کسی مسلمان کے منہ سے نہیںنکل سکتے.بلکہ یقیناً کسی یہودی یا کسی منافق کے ہی ہو سکتے ہیں.یہودی ہی یہ کہا کرتے تھے کہ سترہ مہینے تک تو ادھر منہ کرتے رہے اب دوسری طرف کرنے لگ گئے ہیں.پس یہ الفاظ کسی مسلمان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے.مگر یہ روایت وضع کرتے وقت اُسے اتنا بھی خیال نہ رہا کہ میں الفاظ تو ایسے لکھوں جن سے میری دھوکا دہی پرپردہ پڑا رہے.چنانچہ اس نے روایت تو بنالی مگر خدا تعالیٰ نے اس روایت کے اندر ہی اس سے ایسے الفاظ رکھوا دیئے جن سے اس کی افتراء پردازی کا پردہ فاش ہو گیا اور پتہ لگ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی منافق یا کذاب بول رہا ہے.اُسے اپنے بُغض کی شدت کی وجہ سے اتنا بھی یاد نہ رہا کہ صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمدؐ کے لفظ سے نہیں بلکہ نبی یا رسول کے لفظ سے پکارا کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ساتھ استعمال کیا کرتے ہیں اور گو ’’جامع البیان‘‘ میں ’’اَلنَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ‘‘ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ خود مسلمانوں نے اس روایت کو نقل کرتے وقت لگا لئے ہیں لیکن خواہ اس روایت کے یہ الفاظ ہوں کہ اَنَّ مُحَمَّدًاکَانَ یَسْتَقْبِلُ صَخْرَۃَ بَیْتِ الْمُقَدَّسِ یا یہ الفاظ ہوںکہ اَنَّ النَّبِیَّ صَلیَّ اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ یَسْتَقْبِلُ صَخْرَۃَ بَیْتِ الْمُقَدَّسِ دونوں صورتوں میں اس روایت کا مضمون اپنی ذات میں ایسا گندہ اور ناپاک ہے کہ کوئی سلیم الفطرت انسان اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتا.اِسی طرح بیہقی نے اپنی کتاب’’ دلائل النبوّت‘‘ میں زہری سے روایت کی ہے کہ قبلہ کی تحویل مسجد حرام کی طرف ماہ رجب میں ہوئی تھی جبکہ ہجرت کے بعد سولہ مہینے گذر چکے تھے.وَکَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یُقَلِّبُ وَجْھَہٗ فِی السَّمَآءِ وَھُوَ یُصَلِّیْ نَحْوَ بَیْتِ الْمُقَدَّسِاور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے تو آپ حالتِ نماز میں ہی بار بار اپنا منہ آسمان کی طرف اُٹھاتے تھے اور چاہتے تھے کہ تحویل قبلہ کے بارے میں کوئی خدائی حکم نازل ہو.یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام کی طرف منہ پھیرنے کا حکم نازل فرما دیا اور یہ آیات نازل فرمائیں کہ سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا.اس پر یہود
Page 558
مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ١ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَۘ۰۰۱۴۶ (الٰہی) علم آچکا ہے تو نے اُن کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً اس صورت میں تو ظالموں میں (شمار) ہو گا.تفسیر.فرماتا ہے کہ اگر تم اہل کتاب کو ہر قسم کے نشان دکھائو تو وہ پھر بھی تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کرینگے اور اس میں کیاشبہ ہے کہ اگر وہ تسلیم کر لیتے تو اس کے معنے یہ تھے کہ وہ بنو اسحاق میں سے سلسلۂ نبوت کے ختم ہوجانے کا اقرار کرتے اور اس کے یہ معنے بنتے کہ یہودی مذہب باطل ہو گیا اور اسلام قائم ہو گیا.لیکن یہود اس کے لئے تیار نہیں تھے.پس اُن کی بے دینی اور مذہبی اور قومی مجبوریاں اُن کو اس قبلہ کی طرف نہیں آنے دیتی تھیں اور وہ انکار پر مصر رہتے تھے.یہ آیت بتاتی ہے کہ کبھی کوئی قوم ساری کی ساری نہیں مانا کرتی بلکہ کچھ لوگوں کا ہلاک ہونا ضروری ہوتا ہے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی عزت خدا تعالیٰ کو منظور تھی اس لئے اس نے تئیس برس تک آپ کو کوشاں رکھا اور اس عرصہ میں خبیث گروہ کو اس نے ہلاک کر دیا.اور بعد ازاں اہل عرب کو توفیق عطا فرمائی اور وہ آپؐ پر ایمان لے آئے.بہر حال اختلافات کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک چلتا چلا جائے گا.پس وہ شخص جو اختلافات کو دیکھ کر گھبراتا ہے نہایت بیوقوف ہے.اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْکہ تو بھی ان کے قبلہ کی کسی صورت میں پیروی نہیں کریگا.یہاں قرآنی حسنِ کلام دیکھو کہ اس فقرہ کو کس طرح اعتراض سے بچایا ہے.عام عربی قواعد کے لحاظ سے مَاتَتْبَعُ قِبْلَتَھُمْ کہنا چاہیے تھا مگر اللہ تعالیٰ نے بجائے فعل کے اسم کا استعمال کیا ہے اور فقرہ کی شکل بدل دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے فقرہ کے ساتھ یہ فقرہ بھی تھا کہ وَ لَىِٕنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ کہ وہ ہر قسم کے نشانات دیکھنے کے باوجود تیرے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے.اگر اسی قسم کا جملہ بنایا جاتا اور اس میں اسی قسم کا فعل رکھا جاتا تو اس کے معنے یہ بنتے کہ یہ رسول بھی باوجود دلائل کے اُن کے قبلہ کا پیرو نہیں ہو گا.اور چونکہ یہ قابلِ اعتراض بات تھی اس لئے اس کی بجائے ایک اور چھوٹا سا فقرہ رکھ کر اعتراض دُور کر دیا اور بتا دیا کہ اس رسول کا انکار محض اس وجہ سے ہے کہ اُسے خدا تعالیٰ کی طرف سے دلائل دیئے گئے ہیں.اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ مَااَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَھُمْ یہ تو محض ضِد نظر آتی ہے.لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ضِد نہیں کیونکہ آپؐ نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی طرف منہ کیا تھا.اگر آپ کو یہود سے ضِد ہوتی تو آپ ؐ مکی زندگی میں بھی اور پھر ہجرت کے بعد بھی سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف کبھی منہ نہ