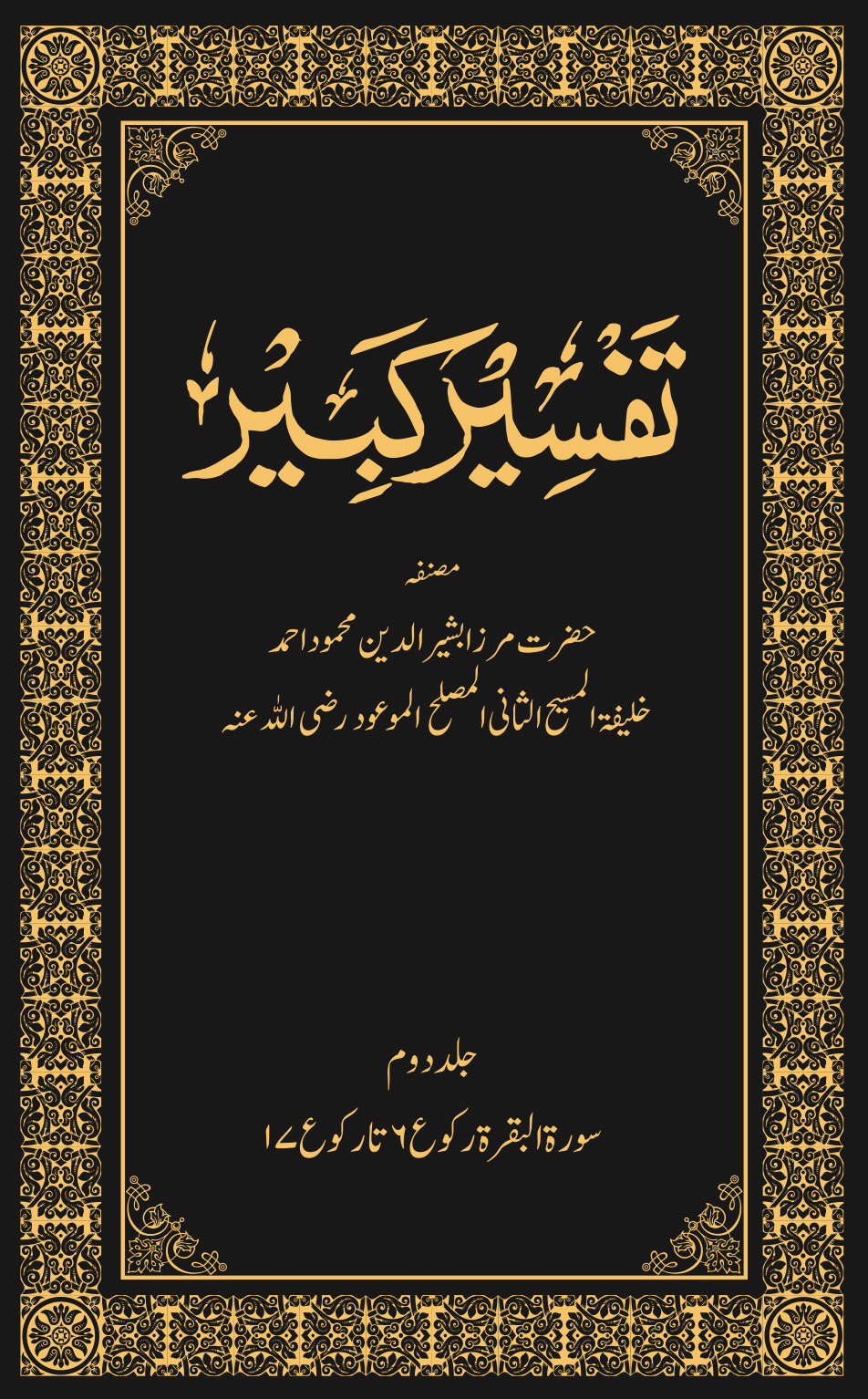Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 2
Content sourced fromAlislam.org
Page 5
يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَنِّيْ اے بنی اسرائیل !میرے اس احسان کو جو میں تم پر کر چکا ہوں یاد کرو اور( اس احسان کو بھی) کہ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۰۰۴۸ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی.حَلّ لُغَات.بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ.ا سرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو بائبل کے بیان کے مطابق ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا.تورات میں آتا ہے ’’کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا.‘‘ (پیدائش باب ۳۲ آیت ۲۸) عبرانی کی ُلغت ANALYTICAL HEBREW AND CHALDEC میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب کے علاوہ ان کی نسل پر (بھی) یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی کبھی بنی اسرائیل کو خالی اسرائیل بھی کہہ دیتے ہیں.عربی اسرائیل کا عبرانی تلفظ یَسْرَائِیْل ہے اور یہ مرکّب ہے یَسر اور اِیل سے.یَسر کے معنے ہیں جنگجو بہادر سپاہی.اور اِیل کے معنے ہیں خدا.پس یَسْرَائِیْل کے معنے ہوئے خدا کا بہادر سپاہی WARRIOR OR SOLDIER OF GOD.عربی زبان کے لحاظ سے یہ لفظ اِسْر اور اِیْل سے مرکب ہے گو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلیۃً عبرانی لفظ ہو اور عربی میں مستعار طور پر استعمال ہوتا ہو لیکن عربی زبان اور عبرانی زبان در حقیقت ایک ہی ہیں اور ہماری تحقیق میں عبرانی زبان عربی کی بگڑی ہوئی صورت ہے یورپین مصنّفوں میں سے بھی بعض اس خیال کے ہیں گو اکثر مذہبی تعصب کی وجہ سے ان دونوں زبانوں کو ایک اور زبان کی شاخ ہی قرار دیتے ہیں بلکہ بعض تو عربی کو عبرانی کی شاخ تک قرار دے دیتے ہیں لیکن یہ موقع اس بحث کا نہیں اس موقع کے مناسب حال اس قدر کہنا کافی ہے کہ عربی اور عبرانی کا اشتراک ایک مسلّمہ حقیقت ہے اسے مدِّنظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ اصل میں عربی ہے اور عبرانی زبان میں اس کی شکل بدل گئی ہے اور ہمزہ نے یاء کی شکل اختیار کر لی ہے.عربی زبان میں اَسَرَالرَّجُلُ کے معنے ہیں قَبَضَ عَلَیْہِ وَ اَخَذَہٗ (اقرب) یعنی فلاں شخص اپنے مدمقابل پر غالب آ گیا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا.ان معنوں کے اعتبار سے اِسْرکے معنے ہوں گے وہ شخص جس کے اندر بہادری اور قوت ہو اور وہ اپنے مدِّمقابل پر غلبہ پا کر اسے اپنی گرفت میں لے لے.اگر عبرانی کے تلفظ اور رسم الخط کو دیکھا جائے تو یَسْر کے معنے ہیں اَللِّیْنُ وَالْاِ نْقِیَادُ (لسان) کسی کی بات کو آسانی سے قبول کر لینا اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا.
Page 6
لفظ اِیْل عربی زبان میں خدا تعالیٰ کے معنوں میں نہیں آتا.ہاں اگر غور کیا جائے تو اس کے حقیقی معنے اللہ تعالیٰ پر ہی صادق آتے ہیں کیونکہ یہ آلَ سے بنا ہے اور آلَ کا اسم فاعل آئِلٌ بنتا ہے اور اِیْل اس سے صفت مُشَبّہ کا صیغہ ہے.آلَ کے معنے ہیں سَاسَ یعنی اس نے نگہداشت کی.چنانچہ کہتے ہیں آلَ الرَّجُلُ اَھْلَہٗ اَیْ سَاسَہُمْ کہ فلاں شخص نے اپنے کنبہ کی پوری نگہداشت کی (اقرب) نیز کہتے ہیں آلَ الْمَلِکُ الرَّعِیَّۃَ کہ بادشاہ نے اپنی رعیّت کی نگرانی رکھی اور رعیّت کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور کی تدبیر کی.نیز کہتے ہیں آلَ عَلَی الْقَوْمِ.وَلِیَ کہ وہ قوم پر بادشاہ ہو گیا.پس آئِلٌ کے معنے ہوئے مدبر، حاکم، بادشاہ اور اِیْلٌ کے معنے ہوں گے ایسی ہستی جس کی ذات میں تدبیر امور اور حکومت اور بادشاہت کی صفات پائیداری کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور یہ صفات سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتیں.کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ازلی اور ابدی ہے.آلَ کے ایک معنے لوٹنے کے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے اِیْل کے معنے ہوں گے کہ وہ ذات جس کے اندر لوٹنے کی صفت پائیداری اور ہمیشگی کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہی معنے بلفظ دیگر تَوَّابٌ کے ہیں.یعنی بار بار رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر لوٹنے والا.الغرض پہلے مادہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے معنے مندرجہ ذیل ہوں گے (۱) ازلی ابدی بادشاہ (یعنی خدا تعالیٰ) کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۲) ازلی ابدی مُدَ بّرہستی کا سخت گرفت رکھنے والا بندہ (۳) بار بار لوٹنے والے کا (یعنی تَوَّاب خدا کا) بہادر بندہ.دوسرے مادہ یعنی یَسْر کے لحاظ سے اسرائیل کے معنے ہوںگے اللہ تعالیٰ کا پورا مطیع و فرمانبردار اور اس کے اخلاق کو اپنے اندر لینے والا.عبرانی زبان چونکہ عربی سے نکلی ہے اس لئے اگرچہ اسرائیل کا تلفظ عبرانی میں بدل گیا اور اِسْرکو یَسر اور اِیْل کو ایل (نرم زبان سے یعنی زبر اور زیر کے درمیانی تلفظ سے) کر دیا گیا اور عربی زبان جو کہ اپنے اصل معنے کا انکشاف کرتی ہے عبرانی نے اسے محدود کر دیا.کیونکہ عبرانی میں اسرائیل کے معنے صرف خدا کے جنگجو بہادر سپاہی کے ہیں لیکن عربی زبان میں جہاں یہ معنے بھی بالوضاحت پائے جاتے ہیں وہاں ایک اور معنے کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ یہ لفظ یَسْرسے بھی صفت مشبّہ کا صیغہ بن سکتا ہے اور یہ لفظ اس خاص حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انبیاء کی فطرت میں پائی جاتی ہے یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لئے سرِ تسلیم َخم رکھنا.گویا اسرائیل اس شخص کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو اور اس کے احکام کے ماننے کے لئے ہر وقت اپنے تئیں تیار رکھے.ان معنوں کی تصدیق تاج العروس والے نے بھی کی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ مَعْنَاہُ صَفْوَۃُ اللہِ وَقِیْلَ عَبْدُاللہِ کہ
Page 7
اسرائیل کے معنے ہیں اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کے احکام کا فرمانبردار.بعض لوگوں نے اس کے معنے سَرِیُّ اللہِ کے کئے ہیں (تاج) سَرِیٌّ کے معنے عربی زبان میں صاحب شرف و مروت اور فَیّاض کے یا معزز شریف سردار کے ہیں.لیکن HEBREW AND ENGLISH LAXICON OF THE OLD TESTAMENT میں اس بات کی تصریح کر دی گئی ہے کہ یَسْرٌ کے حقیقی معنے سَرِیٌّ کے نہیں ہاں اس سے ملتا جلتا مفہوم ہے (اصل بات یہ ہے کہ یَسْرٌ چونکہ جنگجو بہادر کو کہتے ہیں اور ایسا شخص ہی سردارِ لشکر ہو سکتا ہے جو بہادر اور جنگجو ہو اور عرب لوگ بھی ایسے شخص کو سردار مانتے تھے جو صاحبِ شرف اور مروت اور فیاض ہو اور ایسا شخص ہی جنگوں میں پیشرو ہو سکتا تھا تو گویا ان معنوں کے لحاظ سے یَسْرٌ کے معنے سَرِیٌّ کے مشابہ ہو گئے).اُذْکُرُوْا.امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور ذَکَرَ الشَّیْ ءَ (یَذْکُرُ ذِکْرًا وَتَذْ کَارًا) کے معنے ہیں حَفِظَہٗ فِیْ ذِھْنِہٖکسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کر لیا اور جب ذَکَرَ الشَّیْءَ بِلِسَانِہٖ کہیں تو معنے ہوں گے قَالَ فِیْہِ شَیْئًا کہ اس نے کسی بات کے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہا.اور ذَکَرَ لِفُلَانٍ حَدِیْثًا کے معنے ہیں قَالَہٗ لَہٗ کوئی بات بیان کی جب ذَکَرَ مَا کَانَ قَدْنَسِیَ کا فقرہ بولیں تو اس کے معنے ہوںگے فَطَنَ بِہٖ کسی بھولی ہوئی بات کی یاد تازہ ہو گئی.(اقرب) امام راغب لکھتے ہیں اَلذِّکْرُ تَارَۃً یُقَالُ وَیُرَادُ بِہٖ ھَیْئَۃٌ لِلنَّفْسِ بِھَا یُمْکِنُ لِلْاِنْسَانِ اَنْ یَّحْفَظَ مَا یَقْتَنِیْہِ مِنَ الْمَعْرِفَۃِ کہ ذکر کا لفظ بول کر کبھی نفس کی وہ ہیئت مراد لی جاتی ہے جس کے ذریعہ سے انسان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ معلوم شدہ باتوں کو یاد رکھ سکے وَھُوَ کَا لْحِفْظِ اِلَّا اَنَّ الْحِفْظَ یُقَالُ اِعْتِبَارًا بِــاِحْرَازِہٖ وَالذِّکْرُ یُقَالُ اِعْتَبَارًا بِـاِسْتِحْضَارِہٖ.اور ان مذکورہ بالا معنوں میں ذکر کا لفظ حفظ کے لفظ کے ہم معنی ہے ہاں حفظ اور ذکر ہر دو کے مفہوم میں تھوڑا سا امتیاز ہے حفظ کسی شخص کے یاد کرنے پر اس وقت بولیں گے جب وہ ذہن میں بعض باتوں کو جمع کرتا چلا جائے اور ذکر اس کے اس طور پر یاد رکھنے کو کہیں گے کہ اس کو وہ باتیں ُمستحضر رہیں اور جب چاہے انہیں استعمال کر لے وَتَارَۃً یُقَالُ لِحَضُوْرِ الشَّیْ ءِ الْقَلْبَ اَوِالْقَوْلَ اور کبھی دل میں کسی امر کا خیال لانے یا زبان پر کسی بات کے لانے کا نام ذکر رکھا جاتا ہے وَلِذٰ لِکَ قِیْلَ اَلذِّکْرُ ذِکْرَانِ ذِکْرٌ بِالْقَلْبِ وَ ذِکْرٌ بِاللِّسَانِ اسی لئے کہتے ہیں کہ ذکر د۲و طرح ہوتا ہے (۱) قلبی ذکر (۲) زبانی ذکر.وَکُلُّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا ضَرْبَانِ ذِکْرٌ عَنْ نِسْیَانٍ وَ ذِکْرٌ لَاعَنْ نِسْیَانٍ بَلْ عَنْ اِدَامَۃِ الْحِفْظِ کہ خواہ قلبی ذکر ہو یا قولی ہر د۲و کی د۲و د۲و قسمیں ہیں.(۱) بھول جانے کے بعد کسی بات کا یاد کرنا (۲) یا بغیر بھولنے کے یاد رکھنا (مفردات) پس اُذْکُرُوْا
Page 8
کے معنے ہوں گے.تم یاد کرو.نِعْمَتِی.اَلنِّعْمَۃُ کے معنے ہیں(۱) اَلصَّنِیْعَۃُ وَالْمِنَّۃُ احسان.(۲) مَا اُنْعِمَ بِہٖ عَلَیْکَ مِنْ رِّزْقٍ وَ مَالٍ وَغَیْرِہٖ.وہ مال یا رزق یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو بطور انعام ملے.(۳) اَلْمَسَرَّۃُ.خوشی.(۴) اَلْیَدُ الْبَیْضَاءُ الصَّالِحَۃُ ایسا احسان جس میں کوئی کدورت او رکمی نہ ہو.وَفِی الْکُلِّیَاتِ اَلنِّعْمَۃُ فِی اَصْلِ وَضْعِھَا ’’اَلْحَالَۃُ الَّتِیْ یَسْتَلِذُّ بِھَا الْاِنْسَانُ‘‘ وَھٰذَا مَبْنِیٌّ عَلٰی مَا اشْتَھَرَ عِنْدَ ھُمْ مِنْ اَنَّ النِّعْمَۃَ بِالْکَسْرِ لِلْحَالَۃِ وَ بِالْفَتْحِ لِلْمَرَّۃِ.اور کلّیاتِ اَبی البقاء میں یوں لکھا ہے کہ نعمت اصل وضع کے لحاظ سے اس حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان لذّت اُٹھاتا ہے اور یہ اس بناء پر ہے کہ حالت بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں فِعْلَۃٌ اور کسی کام کے ایک ہونے کا اظہار کرنے کے لئے فَعْلَۃٌ کا وزن لاتے ہیں اور نِعْمَۃٌ ن کی زیر سے چونکہ فِعْلَۃٌ کے وزن پر ہے اس لئے اس میں نعمت والی حالت کے معنے پائے جاتے ہیں.وَنِعْمَۃُ اللّٰہِ.مَا اَعْطَاہُ اللّٰہُ لِلْعَبْدِ مِـمَّا لَایَتَمَنّٰی غَیْرَہٗ اَنْ یُّعْطِیَہٗ اِیَّاہُ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے بندے پر وہ احسان ہے جس کے بعد بندہ اس کے متعلق کسی اور سے خواہش نہیں رکھتا.اس کی جمع اَنْعُمٌ اور نِعَمٌ آتی ہے اور جب فُـلَانٌ وَاسِعُ النِّعْمَۃِ کہیں تو اس کے معنے ہوں گے وَاسِعُ الْمَالِ یعنی فلاں مالدار ہے.(اقرب) اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ.اَنْعَمْتُ اَنْعَمَ سے واحد متکلّم کا صیغہ ہے.اَنْعَمْتَ.اِنْعَامٌ سے ہے.انعام کے معنی فضل کرنے اور زیادہ کے ہیں.(اقرب) یہ لفظ ہمیشہ اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جبکہ منعم علیہ یعنی جس پر احسان ہوا ہو عقل والی ہستی ہو.(مفردات) غیرذوی العقول کی نسبت مثلاً گھوڑے بیل کی نسبت کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں شخص نے اس گھوڑے یا بیل پر انعام کیا ہاں یہ کہیں گے کہ فلاں انسان پر انعام کیا.فَضَّلْتُکُمْ.فَضَّلْتُ فَضَّلَ سے واحد متکلّم کا صیغہ ہے اور فَضَّلَہٗ عَلٰی غَیْرِہٖ کے معنے ہیں.جَعَلَ لَہٗ مَزِیَّۃً عَلَیْہِ وَ حَکَمَ لَہٗ بِالْفَضْلِ دوسرے کے مقابل پر ا س کو خوبی کے اعتبار سے عمدہ قرار دیا.اور خوبیوں کی بنا پر اسے دوسروں سے افضل قرار دیا.نیز فَضَّلَہٗ کے معنے ہیں صَیَّرَہٗ اَفْضَلَ مِنْہُ اسے دوسروں کے مقابل ممتاز اور افضل قرار دیا (اقرب)پس فَضَّلْتُکُمْ کے معنے ہوںگے مَیں نے تم کو فضیلت دی اور دوسروں سے ممتاز بنا دیا.اَلْعٰلَمیْن.عَالَمٌ کی جمع ہے اور مخلوق کی ہر صنف اور قسم عَالَم کہلاتی ہے.(مفردات امام راغب) اور عَالَمُوْنَ یا عَالَمِیْنَ کے سوا اس کی جمع عَلَالِمْ یا عَوَالِمْ بھی آتی ہے اور غیر ذوی العقول کی صفات میں سے ون
Page 9
یا یان سے صرف عَالَم یا یَاسَم دو لفظوں کی جمع بنتی ہے.اور عَالَم مخلوق کو اس لئے کہتے ہیں.کہ اس سے خالق کا پتہ لگتا ہے (اقرب) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ عَالَم کی جمع عالَمُوْنَ یا عَالَمِیْنَتب بنائی جاتی ہے جبکہ ذوی العقول کا ذکر ہو.مثلاً انسان، فرشتے وغیرہ.مگر یہ قاعدہ لغت کے بھی خلاف ہے.اور قرآن کریم کے محاورہ کے بھی خلاف.لغت کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے.قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے.قَالَ فِرْعَوْنُ وَ مَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا١ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ.قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْن قَالَ رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآىِٕكُمُ الْاَوَّلِيْنَ.قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ.قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَيْنَهُمَا١ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.(الشعر اء:۲۴تا۲۹) اس آیت میں عَالَمِین میں انسانوں کے سوا آسمان زمین اور ان کے درمیان کی سب اشیاء اور مغرب اور مشرق اور ان کے درمیان کی سب اشیاء کو عالمین میں شامل بتایا گیا ہے.اسی طرح سورۃ حٰمٓ سجدة میں ہے.قُلْ اَىِٕنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا١ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.جَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بٰرَكَ فِيْهَا وَ قَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِيْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ١ؕ سَوَآءً لِّلسَّآىِٕلِيْنَ.(حٰمٓ سجدة:۱۰،۱۱) اس آیت میں بھی زمین اور پہاڑوں وغیرہ کو عالمین میں شامل کیا گیا ہے.اَلْعَالَمِیْنَ کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک حضرت مسیح موعودؑ بھی تحریر فرماتے ہیں.اِنَّ الْعَالَمِیْنَ عِبَارَۃٌ عَنْ کُلِّ مَوْجُوْدٍ سِوَی اللّٰہِ … سَوَاءً کَانَ مِنْ عَالَمِ الْاَرْوَاحِ اَوْمِنْ عَالَمِ الْاَجْسَاِم… اَوْ کَالْشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَغَیْرِ ھِمَا مِنَ الْاَجْرامِ (اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد۱۸صفحہ ۱۳۹،۱۴۰) یعنی عالم سے مراد جاندار اور غیر جاندار سب اشیاء ہیں.اسی طرح سورج ،چاند وغیرہ کی قسم کے اجرام فلکی.غرض سب جاندار یا غیر جاندار اس میں شامل ہیں.جو صرف ذوی العقول کے لئے اسے قرار دیتے ہیں وہ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ (قلم :۵۳) کی آیت سے استدلال کرتے ہیں مگر یہ استدلال درست نہیں.کیونکہ جب اس کا استعمال غیر ذوی العقول کے لئے قرآن کریم میں موجود ہے تو اس آیت کے متعلق صرف یہ کہا جائے گا کہ عام لفظ خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ قرآن کریم میں یہی لفظ اس سے بھی خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے فرماتا ہے وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ(البقرہ :۴۸) اے یہود ہم نے تم کو سب جہانوں پر فضیلت دی ہے حالانکہ مراد صرف اپنے زمانہ کے لوگ ہیں نہ کہ ہر زمانہ کے لوگ.کیونکہ خیر الامم مسلمانوں کو کہا گیا ہے.پس خاص معنوں کا استعمال جبکہ عام معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے اس کے معنوں کو محدود نہیں کرتا.اور حق یہی ہے کہ عَالَمِیْن میں ہر قسم کی مخلوق شامل ہے.خواہ جاندار
Page 10
ہو یا غیرجاندار.تفسیر.آیت ھٰذا میں بنی اسرائیل کو آخری کلام پر ایمان لانے کی طرف مزید توجہ کا مبذول کرانا اس آیت میں ایک اور ذریعہ سے بنی اسرائیل کو خدا تعالیٰ کے آخری کلام پر ایمان لانے کی طرف توجہ دلائی ہے پچھلے رکوع میں تو انہیں اس طرف متوجہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ سے تم نے ایک عہد کیا تھا خدا تعالیٰ نے اس عہد کے متعلق اپنی ذمہ واری پوری کر دی لیکن تم نے اپنی ذمہ واری پوری نہیں کی اس لئے خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم رہ گئے.اب پھر ایک نیا کلام تمہاری کتب کی دی ہوئی خبروں کے مطابق نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آئو تو نئے سرے سے تم پر خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہونے لگیں گے.اب اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ محسن کی محبت تو شریفوں کا خاصہ ہے.خدا تعالیٰ کے تم پر بیحد احسان ہیں تمہاری قوم کو ادنیٰ حالت سے اٹھا کر اس نے ایسی ترقی دی کہ دنیا کی بہترین قوموں میں سے بنا دیا پھر کیوں اس کے احسان کی قدر نہیں کرتے اور اس کے پیغام کو ردّ کرتے ہو.احسان کی قدر کرو اور اپنے محسن سے منہ نہ موڑو.آیت وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَسے مراد ساری قومیں نہیں اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ سے یہ مراد نہیں کہ اگلی پچھلی سب قوموںپر فضیلت دی بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی.قرآن شریف میں اُمّت محمدیہؐ کی نسبت فرمایا ہے کہ یہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہے جیسا کہ فرمایا.كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران :۱۱۱) اور فرمایا.وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا (البقرة :۱۴۴) یہ امر کہ عَلَى الْعٰلَمِیْنَ سے مراد اسی زمانہ کے لوگ ہیںقرآن شریف کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے.اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (آل عمران :۳۴)اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عَالَمِیْنَ سے مراد اپنے اپنے زمانہ کے لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے جن انبیاء اور لوگوں کا ذکر ہے وہ مختلف زمانوں میں گزرے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے ہر ایک تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت رکھتا تھا.کیونکہ اگر آدم ؑ تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ نوح ؑ پر اور دوسرے بزرگوں پر بھی جن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے ان کو فضیلت حاصل تھی.اس صورت میں ان دوسرے بزرگوں کی نسبت کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کو تمام زمانوں کے لوگوں پر فضیلت دی تھی.عالم سے مراد اردگرد یا خاص زمانہ کے لوگ پس بلاشبہ عَالَمِیْنَ سے مراد خاص زمانہ کے لوگ ہیں.ان آیات کے علاوہ ایک اور آیت بھی عَالَمٌ کے معنوں پر روشنی ڈالتی ہے.سورۂ حجر ع۵ میں حضرت لوط کے ذکر میں
Page 11
آتا ہے کہ جب وہ چند مہمانوں کو اپنے گھر لے آئے تو شہروالوں نے ان سے کہا اَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (الحجر:۷۱) کیا ہم نے تجھے غیرقوموں کے لوگوں کو شہر میں لانے سے منع نہیں کیا تھا اس جگہ عَالَمِیْنَ سے مراد اردگرد کے لوگ ہیں نہ کہ اگلی پچھلی نسلوں کے آدمی.پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جہاں عَالَمِیْنَ کا لفظ استعمال ہوا ہے ضروری نہیں کہ اپنے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہو.بلکہ اس کے معنی اردگرد کے لوگ یا اسی زمانہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں.اور یہی دونوں معنے آیت زیرتفسیر میں مراد ہیں.بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت بخشے جانے سے مراد روحانیات کے سب میدانوں میں فضیلت بخشے جانا ہے اس آیت میں فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ فرمایا ہے اَلنّاس نہیں فرمایا.اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی فضیلت کئی رنگ میں تھی.عَالَم کے معنے جیسا کہ سورۃفاتحہ( آیت نمبر ۲)کی تفسیرمیں بتایا جا چکا ہے اس گروہ یا قسم کے ہیں جو خدا تعالیٰ کے لئے بطور نشان ہوتا ہے پس عَالَمِیْنَ کا لفظ مختلف قسم کی خصوصیات رکھنے والے گروہوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے روحانی علوم میں تم کو ترقی ملی تھی.اگر اَلنَّاس ہوتا تو ایک قسم کی ترقی ہی اس سے سمجھی جا سکتی تھی مگر عَالَمِیْنَ کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ روحانیت کے سب میدانوں میں انہیں فضیلت بخشی گئی.کیا بلحاظ شریعت کے ،کیا بلحاظ روحانیت کے ،کیا بلحاظ اخلاقِ فاضلہ کے.غرض ہر قسم کے صاحب کمال لوگ ان میں پیدا ہوئے.جو اس زمانہ کے یا اردگرد کی قوموں کے دوسرے صاحبِ کمال لوگوں پر فضیلت رکھتے تھے.وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ اور اس دن سے ڈرو کہ (جس دن) کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ بن سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ۰۰۴۹ سفارش منظور کی جاوے گی اور نہ اس سے (کسی قسم کا) معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جاوے گی.حَلّ لُغَات.اِتَّقُوْا.اِتَّقُوْا امر مخاطب کا جمع کا صیغہ ہے.اَلْمُتَّقِیْنَ.اَلْمُتَّقِیْنَ متقی کی جمع ہے جو اِتَّقٰی کا اسم فاعل ہے.اِتِّقَاءٌ وَقٰی سے بابِ اِفْتِعال کامصدر ہے.وَقٰی کے معنے ہیں بچایا، حفاظت کی اور اِ تَّقٰی کے معنے ہیں.بچا.اپنی حفاظت کی (اقرب) مگر اس لفظ کا
Page 12
استعمال دینی کتب کے محاورہ میں معصیت اور بُری اشیاء سے بچنے کے ہیں اور خالی ڈر کے معنو ںمیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا.وَقَایَۃٌ کے معنی ڈھال یا اس ذریعہ کے ہیں جس سے انسان ا پنے بچائو کا سامان کرتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اتقاء جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو انہی معنوں میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نجات کے لئے بطور ڈھال بنا لیا.لفظ تقویٰ کا استعمال قران مجید میں اور اس کے معنے قرآن کریم میں تقویٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں حضرت ابوہریرہؓ سے کسی نے پوچھا تو انہوںنے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزرو تو کیا کرتے ہو ،اس نے کہا یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں یا آگے نکل جاتا ہوں.انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے ایک شاعر (ابن المعتز) نے ان معنوں کو لطیف اشعار میں نظم کر دیا ہے وہ کہتے ہیں.؎ خَلِّ الذُّ نُوْبَ صَغِیْرَھَاوَ کَبِیْرَھَا ذَاکَ التُّقٰی وَاصْنَعْ کَمَاشٍ فَـوْقَ اَرْ ضِ الشَّوْکِ یَحْذَرُمَایَرٰی لَا تَحْقِرَنَّ صَغِیْرَۃً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصٰی (ابن کثیر سورۃ بقرۃ زیر آیت ھٰذا) یعنی گناہوں کو چھوڑ دے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہ تقویٰ ہے اور تو اُس طریق کو اختیار کر جو کانٹوں والی زمین پر چلنے والا اختیار کرتا ہے یعنی وہ کانٹوں سے خوب بچتا ہے اور تو چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ کیونکہ پہاڑ کنکروں سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں.یَوْمًا.یَوْم.اس کے معنے مطلق وقت کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے.اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (الحج:۴۸) خدا تعالیٰ کا بعض دن ہزار سال کا ہوتا ہے.ایک شاعر کہتا ہے.ع یَوْمَاہُ یَوْمُ نِدًی وَیَوْمَ طَعَانٍ میرے ممدوح پر دو ہی قسم کے وقت آتے ہیں.یا ِتو وہ سخاوت میں مشغول ہوتا ہے یا دشمنو ںکو قتل کرنے میں.اسی طرح عرب کہتے ہیں.یَوْمَاہُ یَوْمُ نُعْمٍ وَیَوْمُ بُؤْسٍ اَیْ اَلدَّھْرُ.یعنی زمانہ دو حال سے خالی نہیں یا تو انسان کے لئے نعمتیں لاتا ہے یا تکالیف لاتا ہے.(لسان العرب) اسی طرح سیبویہ کا قول ہے کہ عرب کہتے ہیں.اَنَا الْیَوْمَ اَفْعَلُ کَذَا لَا یُرِیْدُوْنَ یَوْمًا بِعَیْنِہٖ وَلٰـکِنَّھُمْ
Page 13
یُرِیْدُوْنَ الْوَقْتَ الْحَاضِرَ (لسان العرب) یعنی جب کہتے ہیں کہ میں آج کے دن اس اس طرح کروں گا.تو اس سے مراد چوبیس گھنٹہ والا دن نہیں ہوتا.بلکہ اس سے مراد صرف موجودہ وقت ہوتا ہے.اسی طرح اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ جو قرآن کریم میں آتا ہے.اس سے بھی مُراد معروف دن نہیں بلکہ زمانہ اور وقت مراد ہے.(لسان العرب) پھر لکھا ہے وَقَدْ یُرَادُ بِالْیَوْمِ اَلْوَقْتُ مُطْلَقًا وَمِنْہُ الحَدِیْثُ تِلْکَ اَیَّامُ الْھَرَجِ اَیْ وَقْتُہٗ (لسان العرب) یعنی کبھی یوم سے مطلق وقت مراد ہوتا ہے جیسے حدیث میں ہے کہ یہ دن فتنہ اور لڑائی کے دن ہیں.مراد یہ کہ یہ فتنہ اور لڑائی کا زمانہ ہے.لَا تَجْزیْ.جَزٰی سے مضارع منفی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اَلْجَزَاءُ (جو جَزٰی کا مصدر ہے) کے معنے ہیں اَلْمُکَافَأَۃُ عَلَی الشَّیْ ءِ کسی بات پر کسی کو کوئی بدلہ دینا اور جب کہیں کہ جَزَی الشَّیْ ءُ تواس کے معنی ہوں گے کَفٰی ایک چیز دوسری چیز کی ساری باتوں میں قائم مقام ہو گئی اور پہلی چیز سے استغناء حاصل ہو گیا (قاموس) نیز کہتے ہیں جَزَیْتُ فُـلَا نًا حَقَّہٗ اور مطلب یہ ہوتا ہے قَضَیْتُہٗ کہ میں نے اس کے حق کو پورا کر دیا (لسان) وَتَاْتِیْ جَزٰی بِمَعنٰی اَغْنٰی اور جَزٰی کے معنے بعض اوقات اَغْنٰی کے ہوتے ہیں یعنی کوئی چیز دوسری چیز کے قائم مقام ہو گئی (لسان) پس لَاتَجْزِیْ نَفْسٌ کے معنے ہوں گے (۱) کوئی نفس قائمقام نہیں بن سکے گا.(۲) کوئی شخص حقوق کو پورا نہیں کر سکے گا.نَفْسٌ.اَلنَّفْسُ کے معنے ہیں (۱) اَلرُّوْحُ.رُوح.(۲)اَلْجِسْمُ جسم.(۳) وَیُرَادُ بالنَّفْسِ اَلشَّخْصُ وَالْاِنْسَانُ بِجُمْلَتِہٖ بعض اوقات نفس کا لفظ بول کر رُوح اور جسم کا مجموعہ انسان اور اس کا خاص تشخص مراد لیاجاتا ہے.(۴) اَلْعَظْمَۃُ.عظمت (۵) اَلْعِزَّۃُ عزت.(۶) اَلْھِمَّۃُ ہمت.(۷) اَ لْاِرَادَۃُ.ارادہ(۸) اَلرَّأْیُ رائے.(اقرب) شَفَاعَۃٌ.شَفَعَ کا مصدر ہے.شَفَعَ کا دوسرا مصدر اَلشَّفْعُ ہے.اور أَلشَّفْعُ کے معنی ہیں ضَمُّ الشَّیْءِ اِلٰی مِثْلِہٖ ایک چیز کے ساتھ اس جیسی دوسری چیز ملا کر ان دونوں کو جمع کر دینا.اور اَلشَّفَاعَۃُ کے معنے ہیں اَلِانْضِمَامُ اِلٰی اٰخَرَ نَاصِرً ا لَّـہٗ وَ سَائِـلًاعَنْہُ کسی شخص کا کسی شخص کے ساتھ اس کی مدد کرنے کی خاطر مل جانا اور اس سے حق کا مطالبہ کرنے والے سے التجا کرنا کہ قصور وار کے قصور کو معاف کر دے.وَ اَکْثَرُ مَا یُسْتَعْمَلُ فِیْ اِنْضِمَامِ مَنْ ھُوَ اَعْلٰی حُرْمَۃً وَ مَرْتَبَۃً اِلٰی مَنْ ھُوَ اَدْنٰی اور شفاعت کے لفظ کا اکثر استعمال ایسے دو اشخاص کے ملنے پر ہوتا ہے جن میں سے ایک عزت و رتبہ کے لحاظ سے اعلیٰ مقام رکھتا ہو اور دوسرا ادنیٰ.اور عزّت و رتبہ رکھنے والا
Page 14
والا شخص ادنیٰ شخص سے اس کی مدد کی خاطر مل جائے.( مفردات) اقرب الموارد میں ہے کہ جب شَفَعَ کا لفظ کسی عدد کے لئے یا نماز کے لئے استعمال کریں تو اس کے معنے ہوتے ہیں صَبَّرَہٗ شَفْعًا اَیْ زَوْجًا اَیْ اَضَافَ اِلَی الْوَاحِدِ ثَانِیًا وَاِلَی الرَّکْعَۃِ اُخْرٰی ایک عدد کے ساتھ دوسرا عدد ملا دیا اور ایک کو دو کر دیا یا ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا کر ان کو دو رکعت بنا دیا.چنانچہ جب یہ کہیں کہ کَانَ وِتْرًا فَشَفَعَہٗ بِآخَرَ تو اس کے معنے ہوتے ہیں قَرَنَہٗ بِہٖ وہ اکیلا تھا اس کے ساتھ ایک اور ساتھی ملا دیا اور اس کو جوڑا کر دیا اور جب شُفِعَ لِیَ الْاَشخَاصُ بصیغہ مجہول کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں اَرَی الشَّخْصَ شَخْصَیْنِ لِضُعْفِ بَصَرِیْ بینائی کی کمزوری کی وجہ سے مجھے ایک شخص کی جگہ دو اشخاص نظر آتے ہیں نیز جب شَفَعَ لَہٗ اَوْ فِیْہِ اِلٰی فُـلَانٍ شَفَاعَۃًکہیں تو اس کے معنی ہوں گے طَلَبَ اَنْ یُّعَاوِنَہٗ اس سے خواہش کی کہ وہ اس کی کسی معاملہ میں مدد کرے اور جب شَفَعَ لِفُـلَانٍ فِی الْمَطْلَبِ کا فقرہ بولیں تو اس وقت یہ مراد ہو گی کہ سَعٰی اس نے کسی مقصد اور ارادہ کو پورا کرنے کے لئے کوشش کی اور جب شَفَعَ لِیْ بِالْعَدَاوَۃِ کا فقرہ بولیں تو معنے ہوںگے اَعَانَ عَلَیَّ اس نے میرے خلاف مدد دی (اقرب) أَلشَّفَاعَۃُ کے معنے کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اَلشَّفَاعَۃُ :.اَلسُّؤَالُ فِی التَّجَاوُزِعَنِ الذُّنُوْبِ مِنَ الَّذِیْ وَ قَعَتِ الْجِنَایَۃُ فِی حَقِّہٖ کہ شفاعت کے معنے ہیں کہ جس کے حق میں کسی سے قصور اور غلطیاں سرزد ہوئی ہوں اس سے یہ خواہش اور سوال کرنا کہ وہ قصور وار سے اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے.وَ قِیْلَ لَا تُسْتَعْمَلُ اِلَّا بِضَمِّ النَّاجِیْ اِلٰی نَفْسِہٖ مَنْ خَافَ مِنْ سَطْوَۃِ الْغَیْرِکہ بعض کے نزدیک شفاعت کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جب کوئی ایسا شخص جو خود نجات یافتہ ہو کسی ایسے شخص کی تائید پر کھڑا ہو جائے جو دوسرے کی سزا سے خائف ہو.(اقرب) عَدْلٌ.اَلْعَدْلُ ضِدُّالْجَوْرِ.عدل کا لفظ جَوْر یعنی ظلم کے بالمقابل بولا جاتا ہے یعنی اس کے معنے انصاف کے ہیں نیز اس کے معنے ہیں(۱) اَلْمِثْلُ مثل.(۲) اَلنَّظِیْرُ نظیر.(۳)اَلْجَزَاءُ بدلہ معاوضہ.(۴)اَلْفِدَاءُ فدیہ.(۵) اَلنَّافِلَۃُ عطیہ یا فرض سے زائد بات.( اقرب) تفسیر.آیت وَاتَّقُوْا … الخ میں بنی اسرائیل کے بعض غلط خیالات کا ردّ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بعض ایسے خیالات کو ردّ کیا گیا ہے جو ان کو بدیوں پر دلیر کرتے تھے اور نیکیوں سے محروم کرتے تھے بنی اسرائیل کے مختلف گروہوں کے غلط خیال اس بارہ میں یہ تھے (۱) ان کے گناہوں کا بار کوئی دوسرا وجود اُٹھالے گا(۲) ان کے بزرگ ان کی شفاعت کر کے انہیں بچا لیں گے (۳) ان کو بعض نیکیاں حاصل
Page 15
ہیں جو ان کے گناہوں سے بہر حال زیادہ رہیں گی اور گناہوں کا بدلہ دے کر بھی وہ جنّت کے مستحق رہیں گے.اس آیت میں ان خیالات کا ردّ کیا گیا ہے تا بنی اسرائیل کو نیکی کا اصل مفہوم معلوم ہو.اور وہ صداقتوں کا انکار کر کے تباہ نہ ہو جائیں.انسانی فطرت میں اعلیٰ روحانی مقام کے حاصل کرنے کا احساس اور اس کا قرآن کریم میں ذکر اس آیت کا مضمون سمجھنے کے لئے اس امر کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ امر مرکوز ہے کہ وہ اعلیٰ رُوحانی مقام کو حاصل کرے متمدّن اقوام ہوں کہ غیر متمدن قبائل سب میں یہ احساسِ کمال کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے.افریقہ کے حبشی ہوں یا مکسیکو کے قدیم باشندے یا آسٹریلیا کے ابتدائی نسلوں کے آدمی.سب اس خواہش سے متاثر نظر آتے ہیں بعض میں یہ احساس معیّن صورت میں پایا جاتا ہے اور بعض میں مبہم صورت میں مگر پایا سب میں جاتا ہے قرآن کریم نے اس احساس کو نہایت لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے فرماتا ہے.وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ١ؕ قَالُوْا بَلٰى ١ۛۚ شَهِدْنَا١ۛۚ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.اَوْ تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ١ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ (الاعراف :۱۷۳،۱۷۴) اور یاد کر جبکہ تیرے رب نے تمام انسانوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو لیا اور انھیں اپنی جانوں پر گواہ بنایا.اور فرمایا کہ کیا مَیں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا ربّ ہے.اے لوگو ! یہ ہم نے اس لئے کیا تا تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس امر سے غافل تھے.یا یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم اُن کے بعد آنے والی نسل تھے.اس لئے لازماً ہم ان کے خیالات سے متاثر ہوئے پھر کیا تو ہم کو اُن جھوٹ بولنے والوں کے جُرم کے بدلہ میں سزا دے گا.ہر انسان توحید کا اثر فطرتاً لے کر پیدا ہوتا ہے شرک کا رنگ اس کے ماںباپ اس پر چڑھاتے ہیں اس آیت میں نہایت لطیف استعارہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے آباء کی پیٹھوں سے ہی یعنی پیدائشی طور پر توحید کا اثر لے کر نکلتا ہے اور شرک کا رنگ بعد میں اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کے ماںباپ اس پر چڑھاتے ہیں.اگر توحید کا اثر خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی پر نہ ڈالا ہوتا تو انسان شرک کرنے میں معذور ہوتا لیکن اس نے توحید کا اقرار پیدائشی طور پر اس کے اندر رکھ کر ہر انسان پر حجت کر دی ہے اب نہ تو وہ ناواقفی کا عذر کرسکتا ہے اور نہ اپنے ماں باپ کے اثر کاعذر پیش کر سکتا ہے.اس فطری اثر کو ہم ہر قوم اور ہر قبیلہ میں محسوس کرتے ہیں ہمیشہ سےانسان اپنے پیدا کرنے والے خدا کا قُرب حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرتا آیا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ لگن فطرت میں
Page 16
پائی جاتی ہے اور کہیں باہر سے نہیں آئی لیکن اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سُستی غفلت یا سہل انگاری کی وجہ سے اس مقصد کو پانے کے لئے سہل راستے تلاش کرتا رہتا ہے فلسفیانہ رنگ کے لوگ اس خواہش کو اس طرح پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اﷲ تعالیٰ نے ہم کو چونکہ اس دنیا کے ماحول میں پیدا کیا ہے.اس لئے وہ ہم سے صرف اس قدر امید کرتا ہے کہ ہم اچھے شہری ہو کر رہیں.اگر ہم اس مقصد کو پورا کر دیں تو اﷲ تعالیٰ کی طرف سے جس قدر ذمّہ واریاں ہیں سب ادا ہو جاتی ہیں.فلسفیوں کی طرف سے عارضی قربانیوں کے ذریعہ سے قَالُوْا بَلٰى کا جواب دینے کی کوشش جو فلسفی ہیں وہ مختلف قسم کی عارضی قربانیوں سے قَالُوْا بَلٰی کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ قربانیاں بعض وقت ظاہر میں بڑی نظر آتی ہیں لیکن حقیقتاً اصل قربانی کا چھوٹا قائم مقام ہوتی ہیں.مثلاً بعض لوگ بجائے مستقل نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے اور رات اور دن اپنے نفس کی اصلاح اور اپنی خواہشات کی قربانی کا کٹھن راستہ طے کرنے کے اپنے بعض اعضاء کاٹ دیتے ہیں اور اسے اس دائمی اور پوری قربانی کا قائم مقام سمجھ لیتے ہیں جو اﷲ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمّہ حقیقی پاکیزگی کے حصول کے لئے مقرر کی ہے بعض لوگ شہوانی جذبات کو دبانے کی طاقت نہ پا کر اس عضو کو جو اس کا ذریعہ ہے کاٹ دیتے ہیں بعض لوگ غیبت جھوٹ اوربدکلامی سے رُکنے کی ہمّت نہ دیکھ کر اپنی زبان کٹوا دیتے ہیں بعض دنیا میں رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کے ذکر کی طاقت نہ پا کر جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں اور کبھی ننگے رہ کر اپنے خیال میں آسائش کی قربانی کرتے ہیں اور کبھی سر کے َبل لٹک کر اپنی ذمّہ واری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ( جیسا کہ ہندوؤں میں دیکھا جاتا ہے) لیکن یہ سب طریقے اپنے اصلی فرائض سے بھاگنے کے مترادف ہیں.اس خیال کا بطلان کہ کامل لوگ تبتّل سے کام لیتے ہیں اگر اﷲ تعالیٰ انسان کی تکمیل کو ان چیزوں پر منحصر رکھتا تو اسے ایک متمّدن انسان پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی.اگر تبتّل یعنی نکاح سے بچنا نیکی کا اصل ذریعہ ہے تو اس کے یہ معنے ہیں کہ دنیا کے کامل کرنے کا ذریعہ اسے فنا کرنا ہے جو کہ بالبداہت باطل ہے.اگر تبتّل ہی انسانی زندگی کا کمال ہے تو سب انسانوں کو کامل ہونا چاہیے اور اگر سب انسان ہی تبتّل اختیار کر لیں تو ایک نسل میں ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبتّل کمال کا ذریعہ نہیں بلکہ کامل لوگ تبتّل سے کام لیتے ہیں.لیکن یہ خیال بھی بالبداہت باطل ہے کیونکہ اس کے معنے تو یہ ہیں کہ کاملوں کی نسل اس دنیا میں نہ چلے اور ناقصوں کی چلے.حالانکہ جانوروں میں اچھے گھوڑے اچھے بیل اور اچھے بھینسے اور اچھے اونٹ اور اچھے بکرے سے نسل لی جاتی
Page 17
ہے.کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے اچھی نسل چلتی ہے.یہی طریق پھل دینے والے درختوں اور پھُول لانے والے پودوں میں اختیار کیا جاتا ہے اور یہی طریق اناج اور سبزی ترکاری پیدا کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے پھر کس طرح ممکن ہے کہ اچھا اناج اچھے بیج سے اور اچھا پھل اچھے درخت کے پیوند سے اور اچھا جانور اچھے سانڈ سے پیدا ہولیکن انسانوں میں سے اچھے لوگوں کو تو بے نسل رکھا جائے اور ناقص انسانوں سے نسل لی جائے.یہ ایسا غلط خیال ہے کہ کوئی معقول انسان اسے مان نہیں سکتا.بعض قوموں میں خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے اور اس کے غضب سے بچنے کے لئے اولاد کی قربانی دی جاتی تھی قریبًا دنیا کے ہر ملک میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں اس رسم کو دُور کرنے کے لئے اﷲ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رؤیا میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا تاکہ ان کا ایمان دنیا پر ظاہر ہو جائے.اور اس رسم کو بھی ہمیشہ کے لئے مٹا دیا جائے.بعض قوموں میں مجرموں یا اجنبیوں کو پکڑ کر قربانی میں پیش کیا جاتا تھا.یہ سب غیر طبعی غیر حقیقی اور غیر معقول خیالات تھے جو ایک طرف خدا تعالیٰ کی صفات اور دوسری طرف انسانی فطرت کی پاکیزگی کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے رہے.اگر یہ لوگ غور سے کام لیتے تو سمجھ جاتے کہ یہ طریق تکمیل کا نہیں ہے تکمیل کا طریق دائمی طور پر برُ ے جذبات سے چوکس رہنا اور ان سے بچنے کے لئے اپنے نفس سے برسرِ پیکار رہنا اور اس کے ساتھ متواتر اﷲ تعالیٰ کی طرف رغبت رکھنا اور اس کی مدد حاصل کرتے رہنا ہے.جہاں مذہب کے متعلق تفصیلی تعلیم نہ رکھنے والے گروہوں میں اوپر کے غلط خیال پھیلے ہوئے ہیں.وہاں مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنی ضمیر کو تسلّی دینے کے لئے اور تکمیل انسانی کی حقیقی جنگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ان تین طریقوں کو ایجاد کر رکھا ہے جن کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا ہے.میرا یہ مطلب نہیں کہ جن قوموں میں کوئی مکمّل شریعت نہیں ان میں یہ خیالات نہیں پائے جاتے ان میں بھی ان خیالات کے پردے میں اپنے نفس کے خواطر کو چھپایا جاتا ہے مگر تفصیلی مذاہب کے پیروؤں میں ان امور کو زیادہ اہمیّت دی جاتی ہے اور دوسرے امور کو کم.اس آیت میں اصل مخاطب بنی اسرائیل ہیں اور وہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اس وقت دو حصوں میں تقسیم تھے (۱) یہود(۲)نصاریٰ.ان دونوں قوموں میں حقیقی نیکی کے مٹ جانے پر تنزّل کے زمانہ میں یہ خیالات زور پکڑ گئے تھے وہ ہر وقت چوکس رہ کر اور رات دن اﷲ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہ کر اس کو پانے کی بجائے یہ سمجھنے لگے تھے کہ اگر وہ شریعت اور آسمانی طریق کو نظر انداز بھی کردیں تو کوئی ہرج نہیں.انھیں یا تو بزرگوں کے کفّارہ کے
Page 18
ذریعہ سے نجات حاصل ہو جائے گی یا بزرگوں کی شفاعت سے یا پھر ان نسلی تعلقات سے جو انھیں حاصل ہیں اور یا ان مالی قربانیوں کی وجہ سے جووہ دنیا میں کرتے رہے ہیں.اب میں الگ الگ ان تینوں امور کے متعلق یہودی اور نصرانی تعلیم کو بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ اقوام غلطی میں پڑ کر نجات کے حقیقی راستہ سے دُور جا پڑی ہیں.پہلا باطل خیال جو یہود و نصاریٰ میں پیدا ہو گیا تھا اور اب تک موجود ہے اور جس کی تردید اس آیت میں قرآن کریم نے کی ہے یہ ہے کہ کوئی اور وجود ان کے گناہوں کا کفّارہ ہو جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جائیں گے.یہود میں یہ خیال ابتداءً قربانی سے پیدا ہوا یعنی جب تقویٰ کی حالت ان میں کمزور پڑ گئی.تو انہوں نے اُن قربانیوں سے جن کا ان کے مذہب میں توبہ کی طرف توجّہ دلانے کے لئے حکم تھا یہ تسلّی حاصل کرنا شروع کر دی کہ یہ قربانیاں ان کے گناہوں کا حقیقی کفّارہ ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السّلام فرماتے ہیں ’’ اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس جیتے حلوان کے سر پر رکھے.اور بنی اسرائیل کی ساری بدکاریوں اور ان کے سارے گناہوں اور خطاؤں کاا قرار کر کے ان کو اس حلوان کے سر پر دَھرے.اور اسے کسی شخص کے ہاتھ جو اس کے لئے معیّن ہو بیابان کو بھجوا دے کہ وہ حلوان ان کی ساری بدکاریاں اپنے اوپر اُٹھا کے ویرانے میں لے جائے گا اور وہ اس حلوان کو بیابان میں چھوڑ دے‘‘ (احبارباب۱۶ آیت ۲۱،۲۲)نیز فرماتے ہیں’’ اور خطا کی قربانی کی بابت ایک بکرا.تاکہ اس سے تمہارے لئے کفّارہ دیا جاوے‘‘ (گنتی باب۲۸آیت ۲۲)یعنی جہاں اور قربانیاں پیش کیا کرو وہاں اپنی خطاؤں کے کفّارہ کے طور پر ایک بکرا بھی قربانی کیا کرو تا وہ بکرا تمہارے لئے کفّارہ ہو جائے اور تمہارے گناہوں کو اپنی قربانی سے مٹا دے.اس میں شک نہیں کہ یہ احکام حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے دوسرے احکام کو دیکھتے ہوئے ان کے یہ معنے کرنے کہ بکرے یا بیل کی قربانی انسانی گناہوں کا حقیقی کفّارہ ہے بالکل درست نہیں.حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام دوسری جگہ فرماتے ہیں’’ یہ وہ شریعتیں اور حقوق اور احکام ہیں جو خداوند تمہارے خدا نے مجھے فرمائے کہ مَیں تمہیں سکھلاؤں تاکہ تم اس سر زمین میں جس کے وارث ہوتے جاتے ہو ان پر عمل کرو تاکہ تُو خداوند اپنے خدا سے ڈرتا رہے اور اس کے سب حقوق اور اس کے سب حکموں کو جو میں تمہیں فرماتا ہوں حفظ کرے، نہ فقط توُ بلکہ ُتو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا زندگی بھر.تاکہ تیری عمر کے دن بڑھائے جاویں.‘‘(استثناء باب۶ آیت ۱‘۲)
Page 19
پھر لکھا ہے ’’ سُن لے اے اسرائیل.خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے.ُتو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ اور یہ باتیں جو آج کے دن میں تجھے فرماتا ہوں تیرے دل میں رہیں اور توُیہ باتیں کوشش سے اپنے لڑکوں کو سکھلا.اور تو اپنے گھر میں بیٹھتے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اُٹھتے وقت ان کا چرچا کر اور تو ان کو نشانی کے لئے اپنے ہاتھ پر باندھ.اور وے تیری آنکھوں کے درمیان ٹیکوں کی مانند ہوں گے انہیں اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھ.‘‘(استثنا باب ۶.آیت ۴ تا ۹) پھر لکھا ہے’’اور تم وہی کرو جو خداوند کی نظر میں راست اور درست ہے.تاکہ تمہارا بھلا ہو.‘‘ (استثنا باب۶ آیت ۱۸) اوپر کے حوالوں سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل کی درستی اور نیکی اور توحید اور شریعت پر انتہا درجہ کا زور دیتے ہیں اور ان پر عمل کو ایسا ضروری قرار دیتے ہیں کہ انہیں تحریر و تقریر سے پھیلانے اور ایک دوسرے کی تلقین کرتے رہنے بلکہ در و دیوار پر لکھ رکھنے تک کی تاکید کرتے ہیں.اس تعلیم کے بعد کیا ایک لمحہ کے لئے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے نزدیک قوم کی قوم کے گناہ ایک بکرے کی قربانی سے دُھل جائیں گے.اگر گناہوں کا دُھلنا اتنا ہی آسان ہے تو پھر اس قدر زور شریعت پر دینے بلکہ حق یہ ہے کہ شریعت نازل کرنے ہی کی ضرورت کیا ہو سکتی تھی.قرآن کریم کا یہود کو کفارہ کا عقیدہ رکھنے پر انتباہ قرآن کریم یہود کے اس غلط خیال کی تردید فرماتا ہے اور یہود کو ہوشیار کرتا ہے اور اس دن سے ڈراتا ہے جبکہ وہ اﷲتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے.اور کوئی جان (قربانی کیا ہوا بکرا) کسی جان (یہودی) کی جگہ اس کے حضور میں قبول نہ کی جائے گی بلکہ اس دن اپنے نفس کی پاکیزگی ہی کام آ سکے گی.جیسا کہ مَیں اوپر بتا آیا ہوں حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی تعلیم جو خطا کی قربانی کے بارہ میں ہے.اس کے معنی صرف یہ تھے کہ بکرے کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجّہ دلائی جائے اور بکرے کی قربانی صرف ایک تصویری زبان میں نصیحت تھی.مگر یہود نے سہل انگاری سے کام لے کر اصل نصیحت کو نظر انداز کر دیا.اور تمثیل کو اصل قرار دیکر نفس کی پاکیزگی کو پیچھے ڈال دیا.اور بکرے کی قربانی کو اپنے لئے کافی سمجھا.بنی اسرائیل پر کفاّرہ کے عقیدہ کا اثر اس قسم کے کفّارہ کا اثر بنی اسرائیل کی طبیعت پر ایسا گہرا تھا کہ جب بخت نصربادشاہِ بابل نے بیت المقدس کو مسمار کر دیا تو چونکہ قربانیاں اسی جگہ ہوتی تھیں ان کو یُوں معلوم ہوا کہ گویا آیندہ گناہ بخشوانے کا کوئی ذریعہ ہی ان کے پاس نہیں رہا اور بہت سے آدمی اس صدمہ کی وجہ سے تارک الدنیا ہو گئے (جوئش انسا ئیکلوپیڈیا زیر لفظ Atonementبحوالہ تو سفتا باب ۱۵.آیت۲) اور ایک بڑے عالم جو شابن حنانیہ نے
Page 20
واویلا کر کے کہا’’ ہم پر افسوس اب ہمارے گناہوں کا کفاّرہ کس طرح ہو گا.‘‘ ( جوئش انسا ئیکلوپیڈیا زیر لفظ Atonement بحوالہ۱۴ سدر۱ باب ۹ آیت ۳۶) مختلف انبیاء کی طرف سے یہودیوں کے خیالی کفارہ کے باطل ہونے کا اعلان مَیں بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کا ہرگز یہ منشاء نہ تھا کہ بکرے کی قربانی گناہوں کا کفّارہ ہو جائے گی بلکہ ان کا منشاء صرف یہ تھا کہ بکرے کی قربانی سے نفس کی قربانی کی طرف توجہ دلائی جائے چونکہ ان کے زمانہ میں لوگ رسوم اور تصویری زبان کے شیدا تھے اﷲ تعالیٰ نے نفس کی قربانی کا مضمون ان کے سامنے رکھنے کے لئے بکرے کی قربانی کی ایک رسم ان میں رکھ دی تاکہ سب قوم کی ایک مقررہ دن گناہوں کے ازالہ کی طرف توجہ ہو جائے مگر انہوں نے تصویری زبان کو تو بھُلا دیا مگر تصویر کو قائم رکھا.بیت المقدس کے گرائے جانے پر جو صدمہ یہود کو ہوا.اس کی وجہ سے انبیائے وقت نے ان کے اس غلط خیال کی تردید شروع کر دی کہ انسان کے گناہ کوئی بیل یا بکرا اٹھا سکتا ہے.چنانچہ ہوسیع نبی فرماتے ہیں’’تم کلمہ ساتھ لے کے خدا وندکی طرف پھرو.اور اُسے کہو کہ ساری بدکاری کو دُور کر اور ہمیں عنایت سے قبول کر.تب ہم اپنے ہونٹوں کے بچھڑے نذر گزرانیں گے.‘‘(ہوسیع باب۱۴ آیت۲) اس آیت میں ہوسیع نبی یہود کو بتاتے ہیں کہ عام بچھڑا یا بکرا کفّارہ نہیں بنتا بلکہ تو بہ اور تسبیح اور تحمید سے انسان گناہ کے اثر سے نجات پاتا ہے.گائے کے پیٹ سے نکلا ہوا بچھڑا نہیں بلکہ تائب کی زبان سے نکلا ہوا بچھڑا حقیقی کفّارہ ہوتا ہے.اس سے چند سال پہلے عاموس نبی نے یہود کو ان قربانیوں پر بھروسہ کرنے سے اس طرح ہوشیار کیا.’’ اور تم ہر چند سو ختنی قربانیوں اور ہدیوں کو میرے آگے گزرانو گے.تو بھی میں انہیں قبول نہ کروںگا اور تمہارے موٹے بیلوں کے شکرانے کے ہدیوں کی طرف متوجہ نہ ہوں گا.‘‘ (عموس باب۵ آیت ۲۲) پھر لکھا ہے کہ اصل علاج توبہ کا یہ ہے کہ ’’ تو ایسا کر کہ عدالت پانی کی طرح بہتی رہے اور راستی بڑی نہر کی مانند.‘‘ (عموس باب ۵ آیت ۲۴) یہودیوں کی کفّارہ کے متعلق ایک اور ایجاد یسعیاہ نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں’’ اب آگے کو جھوٹے ہدیے مت لاؤ.لبان سے مجھے نفرت ہے.نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی کہ مَیں عید اور بیدینی دونوں کی برداشت نہیں کر سکتا ہوں.میرا جی تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری عیدوں سے بیزار ہے وہ مجھ پر ایک بوجھ ہیں.مَیں ان کے اُٹھانے سے تھک گیا.‘‘ (یسعیاہ باب۱ آیت ۱۳،۱۴) پھر لکھا ہے’’ اپنے تئیں دھوؤ.آپ کو پاک کرو اور اپنے بُرے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دُور کرو.بد فعلی سے باز آئو.نیکوکاری سیکھو.انصاف کے پَیرو ہو.مظلوموں کی مدد کرو.یتیموں کی فریادرسی کرو.عورتوں
Page 21
کے حامی ہو اب آؤ کہ ہم باہم حجّت کریں.خداوند کہتا ہے اگرچہ تمہارے گناہ قرمزی ہوویں.پر برف کی مانند سفید ہو جائیں گے اور ہر چندوے ارغوانی ہوویں پر اُون کی مانند اُجلے ہوں گے.‘‘ (یسعیاہ باب۱ آیت ۱۶ تا ۱۸) اسی بارہ میں میکاہ نبی فرماتے ہیں’’ مَیں کیا لے کے خداوند کے حضور میں آؤں اور خدا تعالیٰ کے آگے کیونکر سجدہ کروں.کیا سو ختنی قربانیوں اور یک سالہ بچھڑے کو لیکر اس کے آگے آؤں گا.کیا خداوند ہزاروں مینڈھوں سے یا تیل کی دس ہزار نہروں سے خوش ہو گا.کیا مَیں اپنے پلوٹھے کو اپنے گناہ کے عوض اپنے پیٹ کے پھل کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے ڈالوں گا.اے انسان اس نے تجھے وہ دکھایا ہے جو کچھ کہ بھلا ہے اور خداوند تجھ سے اور کیا چاہتا ہے مگر یہ کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو پیدا کرے اور اپنے خدا کے ساتھ فروتنی سے چلے.‘‘ (میکاہ باب۶ آیت ۶تا۸)اُوپر کے حوالوں سے ثابت ہے کہ یہود کے دلوں میں یہ عقیدہ گھر کر چکا تھا کہ قربانیاں ان کے گناہوں کا کفّارہ ہو جاتی ہیںاور مختلف نبیوں نے انہیں اس عقیدہ سے ہٹانے کی کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اﷲ تعالیٰ بکروں، بیلوں بلکہ پلوٹھے لڑکوں کی قربانی تک سے خوش نہیں ہو سکتا.سابقہ گناہوں کے بد اثر سے بچنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ انسان دل سے اور زبان سے توبہ کرے اور را ستبازی اور نیکوکاری کو اپنے عمل سے پھر قائم کرے.تب اﷲ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے.مگر نبیوں کی یہ تعلیم دیر پا ثابت نہ ہوئی.بکروں اور بیلوں کی قربانی کی عظمت تو یہود کے دلوں سے کچھ کم ہوئی.مگر ایک اور قسم کا کفارہ انہوں نے ایجاد کر لیا اور وہ یہ کہ ہمارے بزرگوں کی تکالیف ہماری قوم کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور اگر نیکوکار کسی زمانہ میں موجود نہ ہوں تو بے گناہ بچوںکو اﷲ تعالیٰ مار کر قوم کے گناہوں کا کفّارہ کر دیتا ہے چنانچہ یہود کی کتب میں لکھا ہے ’’ جس نسل میں نیک لوگ نہ ہوں بے گناہ سکول کے بچوں کو خدا تعالیٰ لے جاتا ہے.‘‘ ( جیوش انسا ئیکلو پیڈیا زیر لفظ Atonement بحوالہ شبات طالمود ) کفارہ کے متعلق مسیحی عقیدہ یہی خیال تھا جس نے بعد میں مسیحی کفّارہ کے عقیدہ کے بننے میں مدد دی.قرآن کریم ان یہود کو مخاطب کر کے اس آیت میں فرماتا ہے کہ اے یہود بنی اسرائیل کوئی جان (خواہ بکرا ہو، خواہ بزرگ ،خواہ بے گناہ سکول کا بچہ ) کسی اور جان ( یہودی ) کی قائم مقام نہیں ہو سکتی اور قرآن کریم کی اس تعلیم سے جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے خود بنی اسرائیل کے نبیوں کو اتفاق ہے.بنی اسرائیل کا دوسرا حصہ وہ ہے جو مسیحی ہو چکا تھا.ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسیح نے صلیب پر موت پا کر مسیحیوں کے گناہوں کو اُٹھا لیا.مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ قربانی جس کا حضرت موسیٰ ؑ نے حکم دیا تھا مسیح کی آمد کی خبر تھی.اور اس سے اس خیال کو تازہ رکھا گیا تھا کہ خدا کا ایک برّہ یعنی مسیح دنیا میں آ کر قربان ہو گا اور دنیا کے گناہ اُٹھالے گا.وہ کہتے
Page 22
الدُّنْیَا.وَالرَّحِیْمُ.رَحِیْمُ الْاٰخِرَۃِ (تفسیر البحر المحیط زیرتفسیر سورة الفاتحۃ) رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ رحمٰن دُنیا کی رحمتوں پر نظر رکھتے ہوئے ہے اور اَلرَّحِیْمُ کا نام آخرت کی رحمتوں پر نظر کرتے ہوئے ہے.اس سے بھی معلوم ہوا کہ رحمٰن کے معنے بلا مبادلہ اور بغیر استحقاق رحم کے ہیں کیونکہ اس قسم کا رحم زیادہ تر اس دُنیا میں جاری ہے اور رحیم کے معنی نیک کاموں کے اعلیٰ بدلہ کے ہیں کیونکہ آخرت مقامِ جزا ہے.تفسیر.سورۃ براء ۃ کے ابتداء میں بسم اللہ کے نہ رکھے جانے کی وجہ قرآن کریم کی سب سورتیں بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے شروع ہوتی ہیں سوائے سورۃ براء ۃ کے مگر اس کے بارہ میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ وہ الگ سورۃ نہیں بلکہ سورۃ انفال کا تتمہ ہے اور اس لئے اس میں الگ بسم اللّٰہ نہیں لکھی گئی.چنانچہ ابو دائود میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ اِنَّ رَسُولَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ لَایَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَۃِ حَتّٰی تُنَزَّلَ عَلَیْہِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (ابو داؤد کتاب الصّلوٰۃ باب مَنْ جَہَرَ بِـبِسْمِ اللہ) یعنی جب ایک سورۃ کے بعد دوسری سورۃ نازل ہوتی تھی تو پہلے بسم اللہ نازل ہوا کرتی تھی اور بسم اللہ کے بغیر رسول کریم صلعم کسی وحی کو دوسری سورۃ قرار نہیں دیا کرتے تھے.حاکم نے مستدرک میں بھی یہ روایت بیان کی ہے.(تفسیرابن کثیر تفسیر سورۃ الفاتحۃ) اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ہر نئی سورۃ سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتی تھی اورپہلی سورۃ کا اختتام ہی تب سمجھا جاتا تھا جب بسم اللہ کے نزول سے دوسری سورۃ کے ابتدا کا اعلان کر دیا جاتا تھا.پس جبکہ بَرَائَ ۃ سے پہلے بسم اللہ نازل نہیں ہوئی یا یُوں کہو کہ اَنْفَال کے بعد بِسْمِ اللّٰہِ نازل ہوکر بَرَاءَ ۃ کی آیات نازل نہیں ہوئیں تو یقیناً وہ الگ سورۃ نہیں ہے بلکہ اَنْفَال کا حصّہ ہی ہے.تمام سورتوں سے پہلے بسم اللہ وحی الٰہی سے لکھی گئی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تمام سورتوں سے پہلے جو بسم اللہ درج ہے وہ وحی الٰہی سے ہے اور قرآن کریم کا حصّہ ہے زائد نہیں.بسم اللہ کا سورۃ فاتحہ کا حصہ ہونے کا ثبوت احادیث سے بسم اللہ کے متعلق بعض علماء نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہر سورۃ کا حصہ بسم اللہ نہیں بلکہ صرف سورۃ فاتحہ کا حصّہ بسم اللہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ کسی سورۃ کا حصّہ بھی بسم اللہ نہیں ہے لیکن یہ خیال درست نہیں.اوّل تو مذکور ہ بالا حدیث ہی اس خیال کو ردّ کرتی ہے دوسرے بہت سی اور احادیث ہیں جن میں بسم اللہ کو رسول کریم صلعم نے سورتوں کا جزو قرار دیا ہے.مثلاً سورۃ فاتحہ کا حصّہ ہونے کے متعلق دارقطنی نے مرفوعاً ابوہریرہؓ سے روایت کی ہے قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَأْ تُمْ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فَاقْرَءُ وْا بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِنَّہا اُمُّ القُرْآنِ وَ اُمُّ الْکِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِیْ وَ بِسْمِ
Page 23
کے لئے تھی تاکہ وہ ان کے لئے کفّارہ ہو جائے.انجیل اور تورات میں کفاّرہ کا ردّ یہ خیال جیسا کہ اوپر یہود کے عقائد کے بارہ میں لکھا جا چکا ہے یہود کے اس خیال کا نتیجہ ہے جو ان میں آخری زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے کہ بزرگ لوگ جو تکلیف اُٹھاتے ہیں اس کا سبب قوم کو گناہوں کی سزا سے بچانا ہوتا ہے مگر یہ خیالات بائبل کی دوسری آیات کے بالکل خلاف ہیں مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں.’’اورجو کوئی اپنی صلیب اٹھاکے میرے پیچھے نہیں آتا میرے لائق نہیں.‘‘(متی باب۱۰ آیت ۳۸) یہی بات بہ تغیرّالفاظ دوسری اناجیل میں بھی ہے.اس آیت کے مضمون سے ظاہر ہے کہ مسیح علیہ ا لسلام اپنی صلیب سے لوگوں کی نجات وابستہ نہیں بتاتے بلکہ ہر اک شخص کا خود صلیب پر لٹکنا اس کی نجات کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی جو موسوی سلسلہ کے بانی تھے اور جن کی تعلیم کو قائم کرنے کا دعویٰ حضرت مسیح کرتے ہیں اس قسم کے کفّارہ کی تردید پائی جاتی ہے.تو رات میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ ا لسلا م پہاڑ پر چالیس راتوں کے لئے گئے اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑا بنا لیا تو اﷲتعالیٰ کا غضب بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کے تباہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا.لکھا ہے.’’ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ مَیں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ ایک گردن کش قوم ہے.اب تو مجھ کو چھوڑ کہ میرا غضب اُن پر بھڑکے اور میں انہیں بھسم کروں.اور میں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤںگا.‘‘ (خروج باب۳۲ آیت ۹،۱۰) اس کے بعد لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ ا لسلام اپنی قوم کی طرف آئے اور شرک پر ناراضگی ظاہر کی.اور پھر لکھا ہے’’ اور دوسرے دن صبح کو یوں ہوا کہ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا اور اب مَیں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں کہ شاید میں تمہارے گناہ کا کفّارہ کروں.چنانچہ موسیٰ خداوند کے پاس پھر گیا اور کہا کہ ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لئے سونے کا معبود بنایا اور اب کاش کہ تو ان کا گناہ معاف کرتا.مگر نہیں تو میں تیری منّت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے دفتر سے جو تو نے لکھا ہے میٹ دے.‘‘(خروج باب۳۲ آیت ۳۰ تا ۳۲) ان آیات سے ظاہر ہے کہ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ ان کے گناہوں کا کفّارہ دینے کا وعدہ کر کے پہاڑ پر گئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ یا تو ان کا گناہ یوُں ہی معاف کر دے نہیں تو مجھے تباہ کر کے ان کے گناہوں کا کفّارہ کر دے.اس التجا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اﷲ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ تُو تو گنہ گار ہے.گنہ گارگنہ گار کا کفّارہ کس طرح ہو سکتا ہے بلکہ اﷲ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ وہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کو اپنے دفتر سے میٹ دُوںگا.‘‘ (خروج باب ۳۲ آیت۳۳) اس جواب سے معلوم ہوتا ہےکہ اﷲ تعالیٰ کسی گنہ گار کے بدلہ میں کسی دوسرے کو سزا نہیں دیتا بلکہ اس کا قانون یہی ہے کہ وہ گنہ گار ہی کو سزا دیتا ہے.اس تعلیم کی موجودگی میں
Page 24
یہ کہنا کہ مسیح اپنی قوم کے گناہوں کے لئے صلیب پر لٹکائے گئے، بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے.شائد کوئی کہے کہ یہ تعلیم حضرت مسیح کے وقت میں منسوخ ہو گئی مگر یہ تو ایک ازلی صداقت ہے اور ازلی صداقتیں منسوخ نہیں ہوا کرتیں.انسانوں کے متعلق احکام بدل سکتے ہیں خدا تعالیٰ کی سنّتیں نہیں بدل سکتیں.مسیحیوں کے کفاّرہ کے متعلق دلائل اور ان کا ردّ قرآن مجید میں جن دلائل پر مسیحیت کفّارہ کی بنیاد رکھتی ہے وہ بھی عقلاً اور نقلاً غلط ہیں.مثلاً یہ کہ انسان کو ورثہ میں گناہ ملا ہے اس لئے وہ اس پر غالب نہیں آسکتا.گویا انسان کی فطرت ہی گنہ گار ہے.قرآن کریم اس کو ردّ فرماتا ہے اور فرماتا ہے.لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْۤ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ(التین: ۵)ہم نے یقیناً انسان کو ہر قسم کی کجی سے پاک قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے.اسی طرح رسول کریم صلی اﷲ علیہ وسلم فرماتے ہیں کُلُّ مَوْلُوْدٍ یُوْلَدُعَلَی الْفِطْرَۃِ (بخاری کتاب الجنائز باب ما قیل فی اولاد المشرکین)ہر بچہ کامل فرمانبرداری کی رُوح لے کر پیدا ہوتا ہے.ورثہ میں گناہ کے ملنے کی حقیقت عجیب بات ہے کہ مسیحی ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ورثہ کے گناہ پر انسان غالب نہیں آ سکتا.اور اس لئے کفّارہ کے لئے ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی کہ جو بلاباپ پیدا ہوا ہو لیکن دوسری طرف وہ اس امر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دو ہی انسان جن کو ورثہ کا گناہ نہ ملا تھا یعنی آدم و حوّا وہ دونوں گنہ گار تھے.اگر وہ دونوں انسان جنہوں نے ورثہ میں گناہ نہ پایا تھا گنہ گار تھے تو پھر یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جن کو ورثہ میں گناہ نہ ملے وہ پاک رہ سکتے ہیں.یہ امر تو تب ثابت ہوتا اگر کئی مثالیں ایسی بھی پائی جاتیں کہ ورثہ میں گناہ نہ پا کر لوگ بے گناہ رہ گئے ہوتے مگر مسیحیوں کے نزدیک تو دو ہی ایسے وجود تھے اور دونوں ہی گنہ گار تھے.تیسرا وجود حضرت مسیح کا ان کے نزدیک ہے لیکن حضرت مسیح کی نسبت یہ کہنا کہ بوجہ بے باپ ہونے کے ان کو ورثہ میں گناہ نہ ملا تھا محض ایک تحکّم کا فیصلہ ہے کیونکہ بچہ صرف اپنے باپ کی قوتوں کو ورثہ میں نہیں لیتا بلکہ ماں کی قوتوں کو بھی ورثہ میں لیتا ہے.نہ معلوم کس نادان نے اس مسئلہ کی ایجاد کرنے والے کے دل میں یہ شبہ ڈال دیا کہ بچہ صرف باپ کی خصلتیں لیتا ہے.بچہ جس طرح باپ کی خصلتیں لیتا ہے اسی طرح ماں کی خصلتیں لیتا ہے.بعض دفعہ بچہ باپ کی شکل پر ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی شکل پر.بعض دفعہ باپ کی قوتوں کا حصّہ اس میں زیادہ ہوتا ہے بعض دفعہ ماں کی قوتوں کا.اور بعض دفعہ برابر برابر.پس اگر مسیح کا باپ نہ تھا تو اس سے یہ کیونکر نتیجہ نکلا کہ ان میں ورثہ کا گناہ نہ آیا تھا.وہ حضرت مریم ؑ کے پیٹ میں پلے اور ماں کی خصوصیات کے وارث ہوئے اور عورت مسیحیوں کے نزدیک اسی طرح گنہ گار ہے.جس طرح مرد.بلکہ بائبل کی رُو سے شیطان نے چونکہ حوّا کے ذریعہ سے آدم ؑ کو
Page 25
ورغلایا تھا.(پیدائش باب۳ آیت ۱ تا ۷) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان عورت کو مرد کی نسبت گناہ کے زیادہ قریب سمجھتا تھا تبھی اس نے براہِ راست آدم کو ورغلانے کی کوشش نہ کی.پس جو بچہ بائبل کے بیان کے مطابق صرف حوّا کی کمزوری لے کر پیدا ہوا.وہ گناہ کے زیادہ قریب تھا بہ نسبت اُن بچوںکے جو آدم کی نسبتی طاقت سے حصّہ لیتے ہیں.خود مسیح علیہ ا لسلام کی اپنی رائے اپنے بارے میں انجیل کے مطابق یہ ہے.لکھا ہے کہ ایک شخص مسیحؑ کے پاس آیا اور اُن سے کہا.’’اے نیک اُستاد مَیں کونسا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں.اس نے اس سے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا.‘‘ (متی باب ۱۹.آیت ۱۶،۱۷)ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح اپنے آپ کو نیک نہیں قرار دیتے.پھر انہیں ایک ہی نیک قرار دے کر کفّارہ کی بنیاد اس پر رکھنی کہاں تک درست فعل ہو سکتا ہے.انجیل میں تحریف کا ایک نمونہ اس جگہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بانیء سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ ا لسلام نے جب اس آیت کو پیش کر کے مسیحیوں کے کفارہ کے عقیدہ پر اعتراض کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو آیت اُنیس۱۹ سو سال تک بقول مسیحیوں کے اناجیل کا حصّہ تھی.تازہ اناجیل میں اُسے بدل دیا گیا ہے.کم سے کم اُردو کے تراجم میں سے اُسے بدل دیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ غلط ہوتا رہا ہے.مسیح علیہ ا لسلام نے یہ نہیں کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے بلکہ یہ کہا تھا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے.مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ انیس۱۹ سو سال تک جو غلطی معلوم نہیں ہوئی وہ بانیء سلسلہ احمدیہ کے اعتراض کے بعد کیونکر معلوم ہوئی ہے.ظاہر ہے کہ یہ ایک دلیرانہ تحریف ہے جو اس زمانہ میں جبکہ پریس کو ایجاد ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں اور کروڑوں اناجیل ہر زبان میں شائع ہو چکی ہیں کی گئی ہے.جو قوم اس قدر دلیرانہ تحریف پریس کی ایجاد کے بعد کر سکتی ہے اس سے پریس سے پہلے تحریف کی کیا کچھ امید نہیں کی جا سکتی.مگر یہ سب کچھ بائبل کے بیان کے مطابق ہے.ورنہ جیسا کہ مَیں نے بتایا ہے اسلام کے نزدیک تو سب ہی بچے نیک فطرت لے کر پیدا ہوتے ہیں.خصوصاً اﷲ تعالیٰ کے انبیاء خواہ مسیحؑ ہوں یاموسیٰ ؑ یا اور کوئی.سب کے سب اﷲ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے مسیح علیہ ا لسلام کو کوئی خصوصیت حاصل نہ تھی.مسیح کے کفاّرہ کی دوسری بنیاد اور اس کا انہدام اس بارہ میں یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسیحؑ کے کفّارہ کی دوسری بنیاد اس پر ہے کہ وہ لوگوں کی خاطر اور ان کے گناہ اُٹھانے کے لئے صلیب پر لٹک کر مرے.صلیب پر لٹک کر مرنے کی نسبت تو آگے چل کر متعلقہ آیات کے ماتحت لکھا جائے گا.اس جگہ کے مناسب حال میں
Page 26
صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ نہ تو مسیح کا اپنی مرضی سے صلیب پر لٹکنا انجیل سے ثابت ہے نہ اُن کا صلیب پر مرنا.انجیل سے اس بات کا ثبوت کہ مسیح نہ صلیب پر اپنی مرضی سے لٹکے اور نہ ہی صلیب پر انہوں نے وفات پائی انجیل میں صاف لکھا ہے کہ حضرت مسیح ساری رات اﷲتعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ وہ اُن کو صلیب سے بچا لے.چنانچہ لکھا ہے ’’ کچھ آگے بڑھ کے ( مسیح علیہ ا لسلام ) مُنہ کے بل گرا.اور دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے گزر جائے.تو بھی میری خواہش نہیں بلکہ تیری خواہش کے مطابق ہو.‘‘ ( متی باب۲۶ آیت ۳۹).کیا عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ جو شخص آسمان سے گنہ گاروں کے گناہ اُٹھانے کے لئے اپنی مرضی سے آیا.وہ اس طرح رو رو کر اور سجدہ میں گر کر اس سے بچنے کی کوشش کرتا رہا.مسیحی کہتے ہیں کہ مسیحؑ نے ساتھ یہ بھی تو کہا کہ خدا کی مرضی ہو.بیشک ایسا ہی لکھا ہے مگر اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ مسیح کی اپنی مرضی لوگوں کے گناہ کا کفاّرہ بننے کی نہ تھی پھر وہ کفّارہ ہو کس طرح گیا.کیا خدا تعالیٰ نے ظلماًایک آکاری شخص کے کندھوں پر لوگوں کا بوجھ ڈال دیا.مسیحؑ کی شدتِ مخالفت تو ہم اس حد تک دیکھتے ہیں کہ جب اُسے صلیب پر لٹکایا گیا تو بقول اناجیل اُس نے کہا’’ ایلی.ایلی.لما سبقتانی.‘‘ (متی باب ۲۷ آیت ۴۶) یعنی اے میرے خدا! اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا.اس حوالہ سے تو اس تشریح کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو مسیحی پہلے حوالہ کی کرتے ہیں یعنی مسیح علیہ ا لسلام نے خدا کی مرضی کو مقدّم کر لیا تھا.کیونکہ انجیل کہتی ہے کہ جب خدا کی مرضی ظاہر ہو ہی گئی اور مسیحؑ صلیب پر لٹک گئے.تو انہوں نے بجائے رضامندی ظاہر کرنے کے خدا تعالیٰ سے نعوذ باﷲ شکوہ کرنا شروع کر دیا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے.خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح کسی صورت میں بھی صلیب پر لٹکایا جانا نہیں چاہتے تھے.پس یہ کہنا کہ وہ انسانوں کے گناہ اُٹھانے کے لئے اس دنیا میں آئے تھے.بالکل باطل ہے.اگر وہ اس غرض کے لئے دنیا میں آئے ہوتے تو کبھی اس واحد ذریعہ سے جو مسیحیوں کے خیال میں لوگوں کو گناہ سے بچانے کا تھا.اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرتے.اب رہا دوسرا سوال کہ کیا مسیح علیہ ا لسلام واقعہ میں صلیب پر فوت ہوئے؟سو اس بارہ میں اختصاراً خود حضرت مسیح علیہ ا لسلام کی شہادت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس فقیہوں اور فریسیوں کا ایک وفد آیا اور درخواست کی کہ انہیں ایک نشان دکھایا جائے.اس پر حضرت مسیح نے فرمایا کہ ’’ اس زمانہ کے بد اور حرامکار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا.کیونکہ جیسا یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا.ویسا ہی ابنِ آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا.‘‘ (متی باب ۱۲ آیت ۳۹،۴۰) یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں
Page 27
زندہ گئے تھے اُس کےپیٹ میں زندہ رہے تھے اور اس کے پیٹ سے زندہ ہی نکلے تھے.پس معلوم ہوا کہ مسیح علیہ السلام بھی قبر میں زندہ ہی گئے اور زندہ ہی رہے اور یہ خیال کہ مسیح صلیب پر مر گئے تھے ایک باطل خیال ہے اور جب وہ مرے ہی نہیں تو اُن کا دوسروں کے گناہوں کی خاطر موت قبول کرنے کا مسئلہ بھی سراسر باطل ٹھہرا.اب ہم حضرت مسیحؑ کو نعوذ باﷲ جھوٹا کہیں یا اُن لوگوں کو جو اُنہیںصلیب پر مار کر قبر میں مُردہ ہی کی حیثیت میں داخل کرتے ہیں اور مرُدہ ہی کی حیثیت میں رکھتے ہیں.یہود پر انسانی قربانی کا اثر اس موقع پر یہ لطیفہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ انسانی قربانی ان معنوں میں کہ لوگ خود کسی انسان کو پکڑ کر اپنے گناہوں کے کفاّرہ کے طور پر قتل کردیں حضرت ابرہیم علیہ ا لسلام کے زمانہ سے موقوف ہو چکی تھی مگر پھر بھی یہود اس کے اثر سے بالکل آزادنہ تھے.چنانچہ کتاب قاضیوں باب۱۱ میں لکھا ہے کہ اسرائیلی سردار افتاح جب بنو عمون سے لڑنے کو نکلا تو اُس نے نذر مانی کہ اگر خدا تعالیٰ اُسے فتح دے تو سب سے پہلی چیز جو اُسے اُس کے گھر سے نکلتی ملے گی وہ اُسے قربان کرے گا.اس کی واپسی پر اُس کی لڑکی جو اُس کی اکلوتی بیٹی تھی.اُسے سب سے پہلے ملی.اور اس نے اُسے قربان کر دیا.اس قسم کی نذر بھی ایک قسم کا کفاّرہ ہوتا ہے.اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گناہ ہماری کامیابی کے راستہ میں روک بنتے ہیں تو اُن کے اثر کو دُور کرنے کے لئے ہم فلاں قربانی پیش کریں گے.خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ کوئی جان کسی جان کی قائم مقام کے طور پر خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش نہیں ہو سکتی نہایت سچا اور عقل کے مطابق دعویٰ ہے.اور خودیہود اور نصاریٰ کی کتب اور حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام اور حضرت مسیح علیہ ا لسلام کے اقوال اس کے مؤید ہیں.اور اس کے برخلاف جو خیالات یہود اور نصاریٰ میں پائے جاتے ہیں صرف ایک باطل خواہش کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں.اور انہوں نے اپنے بزرگوں کو اپنے گناہوں کے بدلہ میں قربانی کےطور پر پیش کر کے ان بزرگوں کی سخت ہتک کی ہے اور گناہ کا دروازہ بہت وسیع کر دیا ہے.شفاعت اور اس کے متعلق یہودیوں کے خیالات دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے یہ ہے کہ اُس دن کوئی شفاعت بھی کسی کی طرف سے قبول نہ کی جائے گی.یہ بھی یہود و نصاریٰ کے رائج الوقت خیالات کے ردّ میں ہے.یہود نسبی شفاعت کے قائل تھے اور اُن کا خیال تھا کہ اُن کا اولاد ابراہیم میں سے ہونا ان کے لئے شفاعت کا موجب ہو گا اور اس تعلق کی وجہ سے اﷲ تعالیٰ انہیں کوئی سزا نہیں دے گا.یا اگر سزادے گا تو نہایت محدود.قرآن کریم میں آگے چل کر اسی صورت میں اُن کے اس دعویٰ کا مندرجہ ذیل الفاظ میں ذکر ہے وَ قَالُوْا
Page 28
لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً(البقرہ :۸۱)یعنی یہود کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ چند گنتی کے دنوں سے زیادہ کسی صورت میں نہ چھوئے گی.یہود کے اس خیال کے متعلق ریورنڈ سیل رکوع۹ کی مذکورہ بالا آیت کے نیچے اپنے ترجمۂ قرآن میں لکھتے ہیں کہ زمانہ حال کے یہود کا یہ ایک مسلّمہ عقیدہ ہے کہ کوئی یہودی سوائے و اتن اور ابیرام اور دہریوں کے دوزخ میں گیارہ مہینوں یا حد سے حد ایک سال سے زیادہ نہ رہے گا.پرانے لٹریچر میں مجھے اس بارہ میں کوئی حوالہ نہیں مل سکا.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ زمانہ کی کتب تو بہت کچھ مٹ چکی ہیں اور زمانۂ حال کے مصنّفین اس غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یہود کلّی طور پر اور قومی طور پر بعث بعد الموت کے منکر ہیں.اور اس وجہ سے بعد الموت زندگی کی نسبت انہوں نے کاوش کر کے یہودی خیالات کو معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی.اسلامی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کم سے کم رسول کریم صلی اﷲ علیہ وسلّم کے زمانہ کے یہود بعد الموت زندگی کے قائل تھے چنانچہ اوپر کی آیت بھی اس پر شاہد ہے اور اَور کئی آیات بھی اس پر شاہد ہیں.اوپر کی آیات کے مفہوم کی تشریح کے سِلسِلہ میں بعض احادیث اسلامی کتب میں آتی ہیں جو اس امر کی مزید وضاحت کر دیتی ہیں.ابنِ اسحاق اور ابنِ جریر حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہر ہزار سال کے مقابل پر ہمیں ایک دن کا عذاب ملے گا.اس کے بعد ہمارا عذاب ختم ہو جائے گا.اسی طرح ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ بعض یہود کا خیال ہے کہ انہیں صرف چالیس دن تک دوزخ کا عذاب ملے گا کیونکہ انہوں نے چالیس دن تک بچھڑے کی پرستش کی تھی (سوائے واتن اور ابیرام کے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے خلاف بغاوت کی تھی.اور وہ ہلاک کر دیئے گئے تھے اور سوائے دہریوں کے ) حضرت ابن عباسؓ کی روایات میں جو دنوں کے بارہ میں اختلاف ہے کسی روایت میں سات دن بیان ہوئے ہیں اور کسی میں چالیس دن.یہ اختلاف یہود کے مختلف قبائل کے مختلف خیالات کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے.بہر حال ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے زمانہ میں بعث بعد الموت کے قائل تھے مگر اُن کا خیال تھا کہ بوجہ اولادِ ابراہیم ہونے کے وہ لمبی سزا نہیں پائیںگے.اور یہ خیال اُن کا کم سے کم کئی صدی پرانا تھا کیونکہ عرب میں رہنے والے یہود چند صدی پہلے سے عرب میں آکر بسے تھے.پس اُن کے وہ خیالات جو دوسرے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں ( دیکھو حوالہ سیل) بہر حال چند صدی پہلے کے ہی تسلیم کرنے پڑیں گے.عہدنامہ قدیم میں بعث بعدالموت کا ذکر غور سے دیکھا جائے تو عہدنامۂ قدیم سے بھی بعد الموت زندگی کا پتہ چلتا ہے.اورحقیقت یہ ہے کہ کوئی مذہب اس بارہ میں تعلیم دینے کے بغیر مکمل کہلا ہی نہیں سکتا.کیونکہ
Page 29
بعد الموت زندگی ہی انسانی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے.اس ذریعہ کے علم سے محروم رکھنا گویا مذہب کی غرض سے محروم رکھنا ہے.پس جو مذہب اس تعلیم میں کوتاہی کرتا ہے اپنے خلاف خود گواہی دیتا ہے.حضرت موسیٰ کی کتاب استثنا باب ۳۱ آیت ۱۶ میں لکھا ہے ’’ تب خداوند نے موسیٰ کو فرمایا دیکھ تو اپنے باپ دادوں کے ساتھ سو رہے گا.‘‘ اس کے معنے صاف ہیں کہ مرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رُوح اپنے باپ دادوں کے ساتھ رکھی جائے گی.کیونکہ جسمانی طور پر موسیٰ علیہ ا لسلام کی قبر وہاں نہیں بنی جہاں کہ اُن کے باپ دادوں کی تھی.کیونکہ وہ جنگل میںفوت ہوئے اور اُ ن کی قبر کا ظاہری نشان تک نہیں ملتا.تورات میں لکھا ہے ’’ آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا.‘‘ ( استثنا باب۳۴ آیت۶) پس معلوم ہوا کہ باپ دادوں کے ساتھ سونے سے مراد اُس جگہ رہنے کے ہی ہیں.جہاں ان کی رُوحیں موت کے بعد رہتی ہیں.اسی طرح تورات میں لکھا ہے کہ اﷲ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام سے کہا ’’ اور اس پہاڑ پر جس پر تو جاتا ہے مر جا اور اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی ہارون حور کے پہاڑ پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں جا مِلا.‘‘ (استثنا باب ۳۲ آیت ۵۰) اس حوالہ سے بھی جسمانی موت کے بعد ایک اور زندگی کا ثبوت ملتا ہے.اور معلوم ہوتا ہے کہ نیک ارواح کسی خاص جگہ پر اکٹھی رکھی جاتی ہیں.ورنہ مرنے کے بعد اپنے باپ دادوں سے جا ملنے کے معنے ہی کیا ہوئے.حضرت ایوب ٫ؑ فرماتے ہیں ’’ کاش میں اُن بچوں کی طرح ہوتا جنہوں نے اُجالا نہیں دیکھا.یعنی بڑی عمر کو نہیں پہنچے.پھر ان کی حالت کی نسبت فرماتے ہیں ’’وہاں شریر ستانے سے باز آتے اور تھکے ماندے چین سے ہیں وہاں اسیرمل کے آرام کرتے ہیں اور ظالم کی آواز پھر نہیں سُنتے.چھوٹے بڑے وہاں برابر ہیں.اور غلام اپنے آقا سے آزاد.‘‘ ( ایوب باب۳ آیت ۱۷ تا ۱۹) اِن آیات سے بھی ایک دوسری زندگی کا پتہ ملتا ہے.یہودیوں کے شفاعت کا عقیدہ تراشنے کی وجہ حضرت داؤد ؑ اﷲ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتےہیں ’’ تو میری جان کو قبر میں رہنے نہ دے گا اور تو اپنے قدّوس کو سڑنے نہ دے گا.تو مجھ کو زندگانی کی راہ دکھلائے گا.‘‘ (زبور باب ۱۶ آیت ۰ ا،۱۱) اسی طرح حضرت داؤد ؑ فرماتے ہیں’’ ان لوگوں سے اے خداوند جو تیرے ہاتھ ہیں دنیا کے لوگوں سے جن کا بَخْرہ اسی زندگانی میں ہے اور جن کے پیٹ تُو اپنی نہانی چیزوں سے بھرتا ہے.ان کی اولاد بھی سیر ہوتی اور وَے اپنی باقی دولت اپنے بال بچوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیںپر مَیں جو ہوں صداقت میں تیرا مونہہ دیکھوں گا.اور جب
Page 30
میں تیری صورت پر ہو کے جاگوں گا تو مَیں سیر ہوؤں گا.‘‘ (زبور باب ۱۷ آیت ۱۴،۱۵) ان آیات سے ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ ا لسلام کے نزدیک بعض لوگ اسی زندگی پر تکیہ کرتے ہیں لیکن مومن بعد از موت زندگی پر دھیان رکھتا ہے کیونکہ وہاں اُسے اﷲ تعالیٰ کی کامل طور پر زیارت ہو گی اور اسکی رُوح اسی دنیا میں خدا کی صورت پر ہو گی یعنی کامل الصفات ہو گی.پھر حضرت داؤد خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ’’ اُس نے ( یعنی داؤد نے ) تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے اس کو عمر کی درازی ابد تک بخشی.‘‘ (زبورباب ۲۱ آیت ۴) ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام اور ان کے بعد کے نبیوں کی تعلیمات سے بعد از موت زندگی کا ثبوت یقینی طور پر ملتا ہے اور جب ہم قرآن کریم کی شہادت کو ملا کر دیکھیں جو دشمن کے نزدیک بھی کم سے کم زمانہ نبوی صلی اﷲ علیہ وسلّم کے متعلق ایک معتبر تاریخی شہادت کی حیثیت ضرور رکھتی ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس بارہ میں زمانہ حال کے محققین کا یہ خیال کہ حضرت مسیحؑ سے پہلے کے اسرائیلی نبیوں کی تعلیم میں بعد از موت زندگی کا ثبوت نہیں ملتا.ایک بودا، کمزور اور بے دلیل خیال ہے اور قلّت تدبّرکا نتیجہ ہے.حق یہ ہے کہ بعد از موت زندگی کی تعلیم یہود میں پہلے سے موجود تھی.اور وہ اپنے اعمال سے ڈرتے ہوئے اس زندگی کے عذاب کا خوف دل سے مٹانے کے لئے کچھ حیلے تراشتے تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ بوجہ نبیوں کی اولاد ہونے کے ان کی شفاعت سے ہم عذاب اُخروی سے یا تو کلّی طور پر بچ جائیں گے یا بہت محدود عذاب ہمیں ملے گا.اﷲ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے.اور فرماتا ہے کہ شفاعت گناہ پر دلیر کرنے کے لئے نہیں ہوتی.ایسی کوئی رعایت تم کو نہ دی جائے گی.پس اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور خود ساختہ خیالات سے فریب کھا کر اپنی عاقبت خراب نہ کرو.یہود کو شفاعت کے بارہ میں غالباً اس امر سے بھی دھوکا لگا کہ اس دنیا میں پہلے بعض الٰہی عذابوں کا اُن کے متعلق فیصلہ ہوا ، پھر نبیوں کی دعا سے وہ ٹل گئے.انہوں نے سمجھا کہ اسی طرح آخرت میں بھی ہو گا.حالانکہ اس دنیا کو اگلے جہان سے کوئی نسبت نہیں.اس دنیا میں عذاب کے ٹلانے سے انسان کو پھر توبہ اور نیکی کا موقع مل سکتا ہے مگر دوسری زندگی تو آخری فیصلہ کا مقام ہے.وہاں اس قسم کی بخشش کے معنے تو یہ بنتے ہیں کہ دنیوی زندگی کو بالکل عبث قرار دےدیا جائے.عیسائیت اورمسئلہ شفاعت شفاعت کا خیال مسیحیوں میں بھی پایا جاتا ہے انجیل میں لکھا ہے’’ اے میرے بچو !میں یہ باتیں تمہیں لکھتا ہوں تاکہ تم گناہ نہ کرو.اور اگر کوئی گناہ کرے تو یسوع مسیح جو صادق ہے باپ کے پاس
Page 31
ہمارا شفیع ہے اور وہ ہمارے گناہوں کا کفاّرہ ہے.فقط ہمارے گناہوں کا نہیں بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی‘‘.(یوحنا کا پہلا خط باب۲ آیت۱) کیا کفاّرہ اور شفاعت ایک ہی چیز ہے؟ اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کفارہ اور شفاعت ایک چیز ہیں؟ اگر ایک چیز ہیں تو پھر ان دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کے کیا معنے ہیں.جہاں تک میرا علم جاتا ہے اس بارہ میں مسیحی کتب خاموش ہیں.مگر کفاّرہ اور شفاعت کے الفاظ کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے.کفاّرہ سے یہ مراد ہے کہ کسی فعل کے ذریعہ سے کسی دوسرے فعل کے اثر کو مٹا دینا لیکن شفاعت کسی فعل یا بدلہ پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس کے معنے سفارش کے ہیں خواہ سفارش کرنے والا گنہگارکے فعل کا کو ئی بدلہ نہ دے وہ جج یا فیصلہ کنندہ سے اپنے تعلق کو جتا کر ایک گنہ گار کے لئے معافی لیتا ہے.میرے نزدیک مسیحیوں نے اس فرق کو نہ سمجھ کر دونوں مطالب کو خلط کر دیا ہے.خلاصہ یہ کہ یہودی بھی اور مسیحی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے اور اب بھی ہیں کہ اُن کے بزرگوں کو اﷲ تعالیٰ سے جو قرب حاصل ہے اس کی وجہ سے اﷲ تعالیٰ یا تو اُن کو عذاب دے گا ہی نہیں ، یا دے گا تو بہت ہی خفیف سا عذاب دے گا.اور اس خیال نے انہیں گناہوں پر دلیر کر دیا ہےاور اس کی وجہ سے الٰہی صداقتوں پر غور کرنے کی طرف سے اُن کی توجہ ہٹ گئی ہے.قرآن کریم اُن کی اس غلطی کو اُن پر آشکار کر کے اُن کی سوئی ہوئی فطرت کو جگاتا ہے اور سچائیوں پر غور کرنے کی قابلیت کو پھر زندہ کرتا ہے.کیا قرآن کریم شفاعت کا منکر ہے؟ اس موقع پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے جو مسیحی مصنّف اسلام اور بانیء اسلام کے متعلق پھیلاتے رہتے ہیں.مسیحی مصنّف اس آیت اور ایسی ہی اَور آیات سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک شفاعت کا مسئلہ مسلّم نہیں ہے اور یہ کہ شفیع ہونے کی مدّعی صرف مسیحؑ کی ذات ہے.رسول کریم صلی اﷲ علیہ وسلم قرآن کریم کے رُو سے شفیع نہیں ہیں (ویری جلد ۲ صفحہ۱۳۰سورۃ بقرۃ زیر آیت ۴۷) اور مسلمان جو اُن کو شفیع کہتے ہیں یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے.جو بقول اُن کے خلاف قرآن کمزور احادیث پر مبنی ہے.یہ خیال مسیحیوں کا غلط فہمی پر مبنی ہے.میں شفاعت کا مضمون تو جو آیات اس کے متعلق ہیں، اُن کے نیچے انشاء اﷲ بیان کروں گا یہاں یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم شفاعت کا منکر نہیں بلکہ اس قسم کی شفاعت کا منکر ہے جو یہودیوں اور مسیحیوں کے عقیدہ کے مطابق ہے ورنہ وہ شفاعت کا قائل ہے.چنانچہ اسی سورۃ میں آگے چل کر یہ الفاظ موجود ہیں مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ(البقرہ :۲۵۶) یعنی کون ہے جو اﷲ تعالیٰ کے پاس اس کی
Page 32
اجازت کے بغیر شفاعت کرے.اسی طرح فرماتا ہے وَ لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ (الزخرف :۸۷) یعنی جن کو یہ لوگ اﷲ کے سوا پکارتے ہیں انہیں شفاعت کا کوئی اختیار نہیں ہاں شفاعت کا حق ہمارے اس بندے کو حاصل ہے جو حق کی گواہی دے رہا ہے اور یہ اس حق کی گواہی دینے والے کو جانتے ہیں.پس قرآن کریم شفاعت کا قائل ہے وہ صرف اس غیر معقول شفاعت کا منکر ہے جو لوگوں کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے اور سچائیوں پر غور کرنے سے باز رکھتی ہے.آیت زیر تفسیر کے الفاظ بھی اس بارہ میں ہماری ہدایت کے لئے کافی ہیں.اس جگہ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شفاعت نہ ہو گی بلکہ یہ فرمایا ہے کہ کسی شخص کی طرف سے شفاعت قبول نہ کی جائے گی گویا مجرم کی طرف سے شفاعت کے پیش ہونے کو رد کیا گیا ہے.مجرّد شفاعت کو ردّ نہیں کیا گیا.وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ میں یہود کی ایک اور غلطی کا ردّ وَلَا یُؤْخَذُ مِنْھَا عَدْلٌ اس جملہ میں یہود و نصاریٰ کی تیسری غلطی کا جوان کو گناہوں پر دلیر کرتی ہے ردّ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ گنہ گار اپنے گناہوں کا بدلہ دے کر گناہوں سے بچ سکتا ہے.یہود اور نصاریٰ دونوں میں گناہوں کا بدلہ دینے کا عقیدہ پایا جاتا ہے.رومن کیتھولک مسیحیوں میں یہود سے بھی زیادہ یہ عقیدہ ہے.جب ان میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ پادری کے پاس جاتا ہے اور وہ کچھ سزا اس کے لئے مقرر کر دیتا ہے جب وہ اس سزا کو بھُگت لے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو گیا.یہود بھی قربانیوں وغیرہ کے ذریعہ سے گناہوں کا بدلہ دینے کے عادی تھے اور ہیں.اسلام گناہوں کا اس قسم کا بدلہ تسلیم نہیں کرتا وہ تو گناہ کی معافی گناہ سے نفرت اور آئندہ کے اجتناب سے متعلق قرار دیتا ہے.اور حق یہی ہے کہ اس کے سوا گناہ کی معافی کی کوئی صورت نہیں.کسی کو قتل کر کے کوئی شخص صدقہ دےدے تو اس سے اس کا یہ گناہ کس طرح معاف ہو جائے گا.یا گرجا میں بیٹھ کر کچھ روزے رکھ لے تو یہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکے گا.اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے بھی بعض غلطیوں کے لئے دوسرے اعمال کو بطور کفارہ قرار دیا ہے لیکن یہ وہ غلطیاں ہیں جو عبادت کی ظاہری شکل کے بارہ میں ہیں.بندوں کی حق تلفی یا خدا تعالیٰ کی حق تلفی کے بارہ میں ایسی کوئی تعلیم اسلام کی نہیں.مثلاً کسی شخص سے حج کا کوئی رُکن رہ گیا تو اس کے بدلہ میں کسی اور نیکی کا حکم دیدیا گیا ہے یا نادانستہ قتل ہو گیا ہے تو اُسے ایک اور عمل بتا دیا گیا ہے یہ اس لئے نہیں کہ اس دوسرے عمل نے گناہ کو دور کر دیا ہے بلکہ اس لئے ہے کہ ظاہری شکل کی غرض کسی اور طرح پوری ہو جائے یا انسان ہوشیار ہو جائے اور آئندہ بے احتیاطی سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو.
Page 33
وَ لَا ھُمْ یُنْصَرُوْنَکی تشریح وَ لَا ھُمْ یُنْصَرُوْنَ یعنی اﷲ تعالیٰ کے عذاب سے ان تین طریق کے سوا کوئی اور غیر طبعی طریق بھی انسان کو بچا نہیں سکتا.اس کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریق ہے کہ انسان صداقت کو سمجھنے اور اُسے قبول کرنے کے لئے پورا زور لگائے اور جہاں تک اس میں طاقت ہے اﷲ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے.اور اس کی آواز پر لبّیک کہتا رہے.پس یہود و نصاریٰ کو چاہیے کہ خود ساختہ طریقوں پر انحصار نہ کریں اور اﷲ تعالیٰ کی طرف سے جو نئی صداقت آئی ہے اُسے قبول کریں ورنہ کوئی اور حیلہ اُن کے کام نہ آئے گا.پہلی آیت اور آیت زیر تفسیر کا تعلق پہلی آیت سے اس آیت کا یہ تعلق ہے کہ پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ تم کو خدا تعالیٰ نے اپنے زمانہ کے لوگوں پر فضیلت دی ہے.اس میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس فضیلت کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم خدا تعالیٰ کے شکر گزار اور فرمانبردار بندے بنتے.مگر تم اس کے برخلاف اس کی اطاعت کا جؤ ااُتار پھینکنے کے لئے قسم قسم کے بہانے تلاش کرنے لگ گئے ہو اور خدا تعالیٰ کے فضل کو پیش کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا اور ناواقفوں کو دھوکا دینا چاہتے ہو.وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ۠ سُوْٓءَ الْعَذَابِ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم کو فرعون کی قوم سے اس حالت میں نجات دی کہ وہ تمہیں بد ترین عذاب يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ١ؕ وَ فِيْ ذٰلِكُمْ دے رہی تھی تمہارے لڑکوں کو( ایک ایک کر کے) ذبح کرتی تھی اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتی تھی اور تمہارے رب بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ۰۰۵۰ کی طرف سے اس( بات) میں (تمہارے لئے) ایک بڑی آزمائش تھی.حَلّ لُغَات.اٰل.اٰل کے معنے ہیں کنبہ.قوم (اقرب) بعض کے نزدیک اٰل اَھْل سے َمقلوُب ہے(مفردات) اور اَھْلُ الرَّجُلِ کے معنے ہیں عَشِیْرَتُہٗ وَ ذَوُوْقُرْبَاہُ.آدمی کا کنبہ اور اس کے اقربا ء.وَاَھْلُ الرَّجُلِ : زَوْجَتُہٗ بعض اوقات اَھْلُ الرَّجُلِ بول کر یہ مراد ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی بیوی.اور جب کسی نبی کے لئے یہ لفظ بولیں اور کہیں اَھْلُ نَبِيٍّ تو اس کے معنے ہوں گے اُمَّتُہٗ نبی کی اُمت.اور اہلِ بیت کے معنے ہیں گھر میں رہنے والے.اور اَھْلُ الْاَمْرِ ان لوگوں کو کہیں گے جو کسی اہم امور پر متعین ہوں.یعنی حُکّام (اقرب) لیکن اَھْل
Page 34
اور اٰل کے استعمال میں فرق کیا گیا ہے.لفظ اٰل بڑے انسانوں کی طرف ہی مضاف ہو گا اور کسی نکرہ کی طرف یا کسی زمانے اور مکان کی طرف نہیں ہو گا( مثلاً یہ نہ کہیں گے کہ آلِ رَجُلیا آلِ زمانہ یا آلِ بَیْت ) لیکن اَھْل کا لفظ ہر ایک کی طرف مضاف ہو سکتا ہے.نیز آل کا لفظ کسی معزز اور شریف ذات کی طرف ہی منسوب ہو گا بمقابل اَھل کے کہ وہ معززاور غیر معزز ہر دو کی طرف مضاف ہو جاتا ہے.یعنی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اَلُ السُّلْطَانِ یعنی بادشاہ کی قوم اور رعیت.لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ آلُ الْخَیَّاطِ درزی کی آل.ہاں اَھْلُ الْخَیَّاطِ کہہ سکیں گے.مگر لفظ اَھْل ہرایک کے ساتھ استعمال ہو سکے گا یعنی اَھلُ السُّلْطَانِ بھی کہہ سکیں گے اور اَھْلُ الْخَیَّاطِ بھی.( مفردات) پس آلِ فرعون کے معنے ہوئے فرعون کی قوم.فِرْعَوْن لَقَبُ کُلِّ مَنْ مَلَکَ مِصْرَ یعنی لفظ فرعون مصر کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا.بعض کے نزدیک ہر سرکش اور متمرّد و مغرور پر فرعون کا لفظ بولا جاتا ہے.اس کی جمع فَرَاعِنَۃٌ ہے.(اقرب) لفظِفرعون فَرْعَنَ سے بنا ہے اور فَرْعَنَ کے معنے ہیں کَان ذَا دَ ھَاءٍ وَ نَکْرٍ کہ اس کے اندر ذہانت اور عقلمندی حد درجہ کی پائی جاتی ہے اور تَفَرْعَنَ فُـلَانٌ کے معنے ہیں طَغٰی وَ تَـجَبَّـرَ سرکش ہوا اور شان و شوکت کا اظہار کیا.اور تَفَرْعَنَ النَّبَاتُ کے معنے ہیں طَالَ وَ قَوِیَ کہ کوئی پودا لمبا اور مضبوط ہو گیا ( اقرب) فرعون مگر مچھ کو بھی کہتے ہیں (اقرب) گویا مصر کے قدیمی بادشاہوں کا لقب ان کی حد درجہ ذہانت اور بڑھی ہوئی طاقت کی وجہ سے فرعون ہو گیا.یَسُوْمُوْنَکُمْ سَامَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے.اور سَامَ فُـلَا نَانِ الْاَمْرَ کے معنے ہیںکَلَّفَہٗ اِیَّاہُ کسی کو مشکل اور بامشقت کام کرنے کا حکم دیا.وَاَکْثَرُ مَا یُسْتَعْمَلُ فِی الشَّرِّ وَالْعَذَابِ اور اس فعل کا اکثر استعمال دُکھ اور شر پہنچانے کے معنوں میں آتا ہے.جب سَامَ الْبَائِعُ السَّلْعَۃَ کہا جائے تو اس کے معنے ہوں گے عَرَضَھَا وَ ذَکَرَ ثَمَنَھَا.سامان کو خریدنے والے پر پیش کیا اور قیمت کا ذکر کیا.جب سَامَہٗ خَسْفًاکہیں تو معنے ہوں گے اَوْلَاہُ اِیَّاہُ وَ اَرَادَہٗ عَلَیْہ ِ کہ اُسے ذِلّت پہنچائی یا اس پر ذلّت پڑنے کی خواہش کی.( اقرب) مفردات راغب میں ہے کہ اَلسَّوْمُ کے اصل معنے ہیںاَلذِّھَابُ فِی ابْتِغَاءِ الشَّيْ ءِ کہ کسی چیز کی تلاش میں جانا فَھُوَلَفْظٌ لِمَعْنًی مُرَکَّبٍ مِنَ الذِّ ھَابِ وَالْاِ بْتِغَاءِ گویا لفظ سَوْم درحقیقت مرکب معنے رکھتا ہے یعنی کسی جگہ جانا اور کسی چیز کو تلاش کرنا لیکن بعض اوقات صرف جانے کے معنے میںاستعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سَامَتِ الْاِبِلُ کہ اونٹ چرنے کے لئے گئے اور کبھی صرف اِبْتِغَاء یعنی چاہنے کے معنے میں.جیسے یَسُوْمُوْنَکُمْ سُوْٓءَ
Page 35
الْعَذَابِ کہ وہ تمہیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے.(مفردات) تاج العروس میں ہے کہ سَامَہٗ کے معنے ہیں اَلْزَمَہٗ وَ جَشَمَہٗ اس کے ذمہ کوئی کام لگایا اور اسے اس کام کے کرنے کی تکلیف دی.(تاج ) اَلْعَذَاب.اَلْعَذَابُ کُلُّ مَاشَقَّ عَلَی الْاِنْسَانِ وَمَنَعَہٗ عَنْ مُرَادِہٖ.عذاب کے معنے ہیں ہر وہ چیز جو انسان پر شاق گزرے اور حصول مراد سے اُسے روک دے.وَفِی الْکُلِّیَاتِ کُلُّ عَذَابٍ فِی الْقُرْآنِ فَھُوَ التَّعْذِیْبُ اِلَّا وَ لْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا طَائِفَۃٌ فَاِنَّ الْمُرَادَ اَلضَّرْبُ.اور کُلِّیَات (ابی البقاء)میں لکھا ہے کہ عذاب سے مراد قرآن مجید میں عذاب دینا ہوتا ہے سوائے وَ لْیَشْھَدْ عَذَابَھُمَا کی آیت کے.وہاں ظاہری سزا مراد ہے (اقرب) اَلْعَذَابُ ھُوَ الْاِیْجَاعُ الشَّدِیْدُ.عذاب کے معنے ہیں سخت تکلیف دینا.فَالتَّعْذِیْبُ فِی الْاَصْلِ ھُوَ حَمْلُ الْاِنْسَانِ اَنْ یَّعْذَ بَ اَیْ یَجُوْعَ وَیَسْھَرَ.اگر مادہ کے لحاظ سے اُسے دیکھا جائے تو اس کے معنے ہیں کہ کسی کو بھوکا اور بیدار رہنے پر آمادہ کرنا.کیونکہ عَذَبُ الرَّجُلُ کے معنے ہیں.اس نے کھانا پینا ترک کر دیا.وَقِیْلَ اَصْلُہٗ مِنَ الْعَذْ بِ.فَـعَـدَّ بْـتُـہٗ اَیْ اَ زَلْتُ عَذْ بَ حَیٰوتِہٖ.بعض نے کہا ہے کہ عذاب عَذْبٌ سے نکلا ہے.جس کے معنے میٹھے پانی کے ہیں.تَعْذِیْب کے معنے اور عَذَّبَ کے معنے ہیں کہ اُسے زندگی کی حلاوت سے محروم کر دیا (مفردات) پس عَذَابکے معنے ہوئے (۱) تکلیف (۲) ایسی چیز جو زندگی کی حلاوت سے محروم کر دے (۳) مقصودِ حیات سے محروم کر دے.پس یَسُوْمُوْنَکُمْ سُوْءَ الْعَذَاب کے معنے ہوں گے (۱) وہ تمہیں بدترین عذاب دے رہے تھے.(۲) وہ تمہیں بدترین عذاب دینا چاہتے تھے.یُذَبِّحُوْنَ.ذَ بَّـحَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ذَ بَّـحَ ذَ بَـحَ سے باب تفعیل ہے.ذَ بَـحَ کے معنے ہیں شَقَّ پھاڑ دیا.نیز اس کے معنے ہیں فَتَقَ توڑ دیا.خَنَقَ گلاگھونٹ کر مار دیا.نَحَرَ ذبح کیا.(اقرب) لسان میں ہے اَلذَّبْحُ قَطْعُ الْحُلْقُوْمِ.ذَ بَـحَ کے معنے ہیں گلاکاٹنا (لسان).تاج العروس میں ہے اَلذَّ بْـحُ.اَلْھَلَاکُ کہ ذبح کے ایک معنی ہلاک کر دینے یا مار دینے کے ہیں (تاج).اس جگہ ذَ بَـحَ کے معنے مارنے یا گلا گھونٹ کر مارنے کے ہیں.پس یُذَبِّحُوْنَ اَبْنَائَکُمْ کے معنے ہوں گے (۱) وہ تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے (۲) وہ تمہارے لڑکوں کو گلاگھونٹ کر مار دیتے تھے.یَسْتَحْیُوْنَ.اِسْتَحْیَا سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِسْتَحْیَاہُ کے معنے ہیں اَبْقَاہُ حَیًّا
Page 36
اُسے زندہ رہنے دیا.نیز لکھا ہے قَالَ اللِّحْیَانِیُّ اِسْتَحْیَاہُ اِسْتَبْقَاہُ وَلَمْ یَقْتُلْہُ کہ لحیانی کہتے ہیں.اِسْتَحْیَاہ کے معنے ہیں کہ اُسے زندہ رہنے دیا اور اُسے قتل نہ کیا (لسان) پس یَسْتَحْیُوْنَ نِسَائَکُمْ کے معنے ہوں گے کہ وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور قتل نہ کرتے تھے.بَـلَاءٌ.بَلَوْتُ الرَّجُلَ ( بَـلَاءً وَ بَلْوًا) وَابْتَلَیْتُہٗ کے معنے ہیں اِخْتَبَرْتُہٗمیں نے اس کا امتحان لیا اور اِبْتَـلَاہُ اللہُ کے معنے ہیں اِمْتَحَنَہٗ.اﷲ نے اس کا امتحان لیا اور اس سے اسم اَلْبَلْوٰی.اَلْبَلْوَۃُ اَلْبَلِیَّۃُ اور اَلْبَلَاءُ آتا ہے یعنی امتحان.نیز لکھا ہے اَلْبَـلَاءُ یَکُوْنُ فِی الْخَیْرِ وَ الشَّرِّکہ بلاء کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں.بلائے خیر بھی اور بلائے شر بھی.چنانچہ کہتے ہیں اِبْتَلَیْتُہٗ بَـلَاءً حَسَنًا وَّ بَـلَاءً سَیِّئًاکہ میں نے اس کا اچھا امتحان لیا اور بُرا امتحان لیا.پھر لکھا ہے وَ اللہُ تَعَالٰی یَبْلِی الْعَبْدَ بَـلَاءً حَسَنًا وَیَبْلِیْہِ بَـلَاءً سَیِّئًا کہ اﷲ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان ہر دو طرح سے لیتا ہے بلائِ انعام سے بھی اور بلائِ تکلیف سے بھی.نیز اَلْبَـلَاءُ کے معنے انعام کے بھی لکھے ہیں (لسان) اَلْبَلَاءُ کے اصل معنے امتحان کے ہوتے ہیں لیکن امتحان چونکہ کبھی انعام کے ذریعہ سے اور کبھی سزا کے ذریعہ سے لیا جاتا ہے اس لئے بَلَاء کے اندر دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں.انعام کا امتحان بھی اور تکلیف کا امتحان بھی.چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے.وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّيِّاٰتِ (الاعراف :۱۶۹) عَظِیْمٌ.عَظِیْمٌ.عَظُمَ سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور عَظُمَ الشَّيْءُ عِظَمًا وَ عَظَامَۃً کے معنے ہیں کَبُرَ کوئی چیزبڑی ہو گئی.جب کہیں کہ عَظُمَ الْاَمْرُ عَلٰی فُـلَانٍ تو اس کے معنے ہوتے ہیں شَقَّ وَ صَعُبَ یعنی فلاں کام اس پر برداشت کرنا مشکل اور گراں ہو گیا ( اقرب) پس عَظِیْمٌ کے معنے ہوں گے (۱) بڑا (۲) گراں.مشکل.تفسیر.بنی اسرائیل پر خدا تعالیٰ کے متعدد احسانات اور ان کی تفصیل اس آیت سے ان احسانات کی تفصیلات گنوانی شروع کی ہے جو ایک لمبے عرصہ سے بنی اسرائیل پر ہوتے چلے آئے تھے.چنانچہ پہلا احسان یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل مصر کے فراعنہ کے ماتحت غلاموں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے تب اﷲ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ کو بھیج کر اس عذاب سے اُن کو نجات دلوائی.پہلا احسان بنی اسرائیل کو غلامانہ زندگی سے نجات دلوانا بائبل میں بنی اسرئیل کی اس غلامانہ زندگی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے.’’ مصر میں ایک نیا بادشاہ جو یوسف کو نہ جانتا تھا پیدا ہوا اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں.آؤ ہم ان سے دانشمندانہ معاملہ کریں تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل جاویں اور ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جاویں.اِس
Page 37
لئے انہوں نے اُن پر خراج کے لئے محصّل بٹھلائے تاکہ انہیں اپنے سخت کاموں کے بوجھوں سے ستا ویں…اور مصریوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر سختی کی.اور انہوں سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سب قسم کی خدمت کھیت کی کروا کے ان کی زندگی تلخ کی.ان کی ساری خدمتیں جو وہ کراتے تھے مشقّت کی تھیں.‘‘ (خروج باب ۱ آیت ۸ تا ۱۴) يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ کے معنے لڑکوں کو ہلاک کرنے کے يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ رعمسیس ثانی جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ ؑ پیدا ہوئے بنی اسرائیل کا سخت دشمن تھا اور بنی اسرائیل کی ترقی دیکھ کر اس نے ان کے لڑکے قتل کرنے کا حکم دےدیا تھا.مگر دائیوں کی نرم دلی کی وجہ سے اِس ارادہ میں وہ پوری طرح کامیاب نہ ہوا اور آخر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکے دریا میں پھینک دئے جایا کریں.اور لڑکیاںبچا لی جائیں.‘‘(خروج باب۱ آیت ۲۲) طالمود میں بھی اسی مضمون کی روایات ہیں.اسی طرح اعمال باب ۷ آیت ۱۹ میں لکھا ہے:.’’ یہاںتک کہ اس نے (فرعون نے ) ان کے لڑکوں کو پھینکوا دیا تاکہ وے جیتے نہ رہیں.‘‘ بعض لوگوں نے اِس آیت میں ذبح کے لفظ سے دھوکا کھایا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک بنی اسرائیل کے بچوں کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا.حالانکہ تاریخ کی شہادت اس کے خلاف ہے.اِن لوگوں کے دھوکا کھانے کی یہ وجہ ہے کہ ذبح کا لفظ گلاکاٹ دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے.لیکن اس کے معنے ہلاک کر دینے کے بھی ہیں.جن کے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے اِن معترضوں کو دھوکا لگا ہے.چنانچہ تاج العروس جلد ۲ صفحہ ۱۳۸ پر لکھا ہے.وَالذَّ بْـحُ: اَلْھَـلَاکُ یعنی ذبح کے ایک معنی ہلاکت کے بھی ہیں.پس یُذَ بِّـحُوْنَ اَبْنَـآئَـکُمْ کے یہ معنے نہیں کہ وہ تمہارے لڑکوں کا گلا کاٹ دیتے تھے بلکہ یہ معنے ہیں کہ وہ تمہارے لڑکوں کو ہلاک کرتے تھے.چنانچہ سورۂ اعراف آیت ۱۴۲ میں یُذَبِّحُوْنَ اَبْنَـآئَـکُمْ کی بجائے یُقَتِّلُوْنَ اَبْنَـآئَـکُمْ کے الفاظ رکھ کر قرآن کریم نے یُذَ بِّـحُوْنَ کے معنے خود ہی کر دیئے ہیں کہ اِس سے مراد گلا کاٹنا ہی نہیں بلکہ مار دینا ہے خواہ کسی طرح سے ہو.بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ایسے عذاب سے نجات دینے میں تمہارے لئے بڑا انعام تھا.یہ نجات بہت سے انعامات کا موجب ہوئی.
Page 38
وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ۠ وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کوپھاڑا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہاری نظروں وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ۰۰۵۱ کے سامنے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا.حَلّ لُغَات.فَرَقْنَا.فَرَقَ سے متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے.اور فَرَقْنَابِکُمُ الْبَحْرَ کے معنی ہیں فَلَقْنَاہُ ہم نے سمندر کو پھاڑا.(اقرب) تَنْظُرُوْنَ.نَظَرَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے.اور نَظَرَہٗ وَ اِلَیْہِ کے معنے ہیں اَبْصَرَہٗ وَ تَأَ مَّلَہٗ بِعَیْنِہٖ کسی پر اچانک نظر پڑنے کے بعد غور سے اسے دیکھنے کے لئے ٹِکٹکی لگائی.نیز نَظَرَہٗ کے معنے ہیں.مَدَّ طَرْفَہٗ اِلَیْہِ رَآہُ اَوْ لَمْ یَرَہٗ کسی کی طرف آنکھ اٹھائی.خواہ پھر اسے دیکھ سکایا نہ دیکھ سکا.(دونوں حالتوںمیںنَظَرَ کا لفظ اس پر بول سکتے ہیں) نیز کہتے ہیں نَظَرَ فِی الْاَمْرِ نَظَرًا.اور معنے یہ ہوتے ہیں کہ تَدَبَّرَہٗ وَ تَفَکَّرَ فِیْہِ یُقَدِّرُہٗ وَ یُقِیْسُہٗ نظر کے یہ بھی معنے ہیں کہ کسی امر پرغور کیا اور کسی معاملہ کو کسی اور معاملہ پر قیاس کر کے غور و فکر سے اپنی رائے قائم کی.جب نَظَرَبَیْنَ النَّاسِ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں حَکَمَ وَ فَصَلَ دَعَاوِیْھِمْ لوگوں کے جھگڑوں کا سوچ بچار کر فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ ان میں سے اپنے دعوے میں صادق کون تھا اور جب نَظَرَ لِلْقَوْمِ بولا جائے تو اس کے معنے یہ ہوں گے دَنٰی لَھُمْ وَ اَعَانَھُمْ کہ لوگوں کو مصائب و مشکلات میں پھنسا دیکھ کر دل میں رحم پیدا ہوا اور ان کی مدد کی.نَظَرَالشَّیْءَ کے ایک معنے اِنْتَظَرَہٗ کے بھی ہیں یعنی انتظار کیا.نیز اہل عرب کہتے ہیں دَارِیْ تَنْظُرُ اِلٰی دَارِ فُـلَانٍ اَیْ تُقَابِلُھَا.یعنی میرا گھر فلاں کے گھر کے بالمقابل ہے.(اقرب) پس تَنْظُرُوْنَ کے معنے ہوں گے (۱) تم آلِ فرعون کا غرق ہونا دیکھ رہے تھے.(۲)تم آل فرعون کے غرق ہونے کو دیکھ کر ان کے دعاوی کے جھوٹا ہونے اور اپنے دعاوی کے سچا ہونے کا فیصلہ کر رہے تھے.(۳) تم آلِ فرعون کے غرق ہونے پر رحم کھا رہے تھے کہ کاش وہ بدیاں نہ کرتے اور ہلاکت تک نوبت نہ پہنچتی.(۴) تم ان کی ہلاکت کے منتظر تھے.(۵) ہم نے آلِ فرعون کو اس وقت غرق کر کے ہلاک کر دیا جب کہ تم بالکل ان کے بالمقابل تھے.تفسیر.فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کے معنی کرنے میں مفسرین کا غلطی کھانا اور اس کے صحیح معنے فَرَقْنَابِکُمُ الْبَحْرَ کے لفظی معنے ہیں.جبکہ ہم نے تمہارے ذریعہ سے سمندر کو پھاڑا اور ان معنوں سے دھوکا کھا کر
Page 39
اکثر مفسرین نے آیت کے یہ معنے کئے ہیں کہ بنی اسرائیل دریا پھاڑنے کا ذریعہ تھے.ان کو دریا میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو جوں جوں وہ آگے بڑھتے تھے دریا کا پانی سمٹتا جاتا تھا لیکن یہ معنے خود قرآن کریم کے الفاظ سے غلط ثابت ہوتے ہیں.قرآن کریم میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ١ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ( الشعراء :۶۴)یعنی ہم نے موسیٰ ؑ کو وحی کی کہ تو سمندر پر سونٹا مار.جب اس نے سونٹا مارا تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک اونچے ٹیلے کی طرح نظر آتا تھا.اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کے پھٹنے کا ذریعہ ظاہر میں سونٹا تھا نہ کہ بنی اسرائیل.پس یہ معنے کہ بنی اسرائیل کے ذریعہ سے سمندر کو پھاڑا باطل ہوئے.اب یہ سوال ہے کہ اس کے معنے کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بَاء عربی زبان میں تعلیل اور سَبَبِیَّتْ کے لئے بھی آتی ہے.اور آیت کے معنے یہ ہیں.کہ ہم نے تمہارے سبب سے سمندر کو پھاڑا.یعنی تمہیں نجات دینے کے لئے ہم نے ایسا کیا.دوسرے الفاظ میں فَرَقْنَالَکُمُ الْبَحْرَ کے معنوں میں فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ آیا ہے.( دیکھو بحر محیط، کشّاف، شرح مِائَۃُ عَامِل زیر آیت ھٰذا) فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَمیں بنی اسرائیل کے سمندر سے ہو کر بچ نکلنے کے معجزہ کی طرف اشارہ وَاِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ اِس آیت میں اِس معجزہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ ؑکے لئے اﷲ تعالیٰ نے اُس وقت دکھایا جبکہ حضرت موسیٰ ؑ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر شام کی طرف لے جا رہے تھے.اور ان کو واپس لے جانے کے لئے فرعون اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کر رہا تھا.خروج باب ۱۴ آیت ۲۱ تا ۳۱ میں لکھا ہے:.’’ پھر موسیٰ نے دریا پر ہاتھ بڑھایا.اور خداوند نے بہ سبب بڑی پوربی آندھی کے تمام رات میں دریا کو چلایا اور دریا کو سُکھا دیا اور پانی کو دو حصے کیا.اور بنی اسرائیل دریا کے بیچ میں سے سوکھی زمین پر ہو کے گزر گئے.اور پانی کی ان کے دہنے اور بائیں دیوار تھی.اور مصریوں نے پیچھا کیا.اور ان کا پیچھے کئے ہوئے وَے اور فرعون کے سب گھوڑے اور اس کی گاڑیاں اور اس کے سوار دریا کے بِیچوں بیچ تک آئے.اور یوں ہوا کہ خداوند نے پچھلے پہر اس آگ اور بدلی کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی.اور مصریوں کی فوج کو گھبرا دیا.اور ان کی گاڑیوں کے پہیوں کو نکال ڈالا.ایسا کہ مشکل سے چلتی تھیں.چنانچہ مصریوں نے کہا.کہ آؤ اِسرائیلیوں کے مُنہ پر سے بھاگ جاویں.کیونکہ خداوند اِن کے لئے مصریوں سے جنگ کرتا ہے.اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ دریا پر بڑھا.تاکہ پانی مصریوں
Page 40
اور ان کی گاڑیوں اور ان کے سواروں پر پھر آوے.اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ دریا پر بڑھایا.اور دریا صبح ہوتے اپنی قوت اصلی پر لَوٹا.اور مصری اس کے آگے بھاگے.اور خداوند نے مصریوںکو دریا میں ہلاک کیا.اور پانی پھرا.اور گاڑیوں اور سواروں اور فرعون کے سب لشکر کو جو ان کے پیچھے دریا کے بیچ آئے تھے چھپالیا.اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا.پر بنی اسرائیل خشک زمین پر دریا کے بیچ میں چلے گئے.اور پانی کی ان کے داہنے اور بائیں دیوار تھی.سو خداوند نے اُس دن اسرئیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے یوں بچایا.اور اسرائیلیوں نے مصریوں کی لاشیں دریا کے کنارے پر دیکھیں.اور اسرائیلیوں نے بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی.اور لوگ خداوند سے ڈرے.تب خداوند پر اور اس کے بندے موسیٰ پر ایمان لائے.‘‘ قرآن کریم کے دیگر مقامات میں واقعہ ھٰذا کا ذکر قرآن کریم میں یہ واقعہ علاوہ اِس آیت کے سورۃ شعراء ع۴ اور سورۂ طٰہٰ ع۴ میں بھی بیان ہوا ہے.چنانچہ سورۂ شعراء میں آتا ہے.فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ١ؕ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ(الشعراء:۶۴) یعنی ہم نے موسیٰ سے وحی کی کہ تو سمندر پر سونٹا مار.جب اس نے سونٹا مارا تو سمندر پھٹ گیا.اور ہر ٹکڑا ایک اونچے ٹیلے کی طرح نظر آتا تھا.پھر سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے.وَ لَقَدْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى١ۙ۬ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا١ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّ لَا تَخْشٰى.فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.وَ اَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَ مَا هَدٰى.(طٰہٰ :۷۸ تا۸۰) یعنی ہم نے موسیٰ سے وحی کی کہ ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکال لے جاؤ.اور سمندر میں سونٹا مار کر ان کے لئے خشک رستہ بنا دو.تم اس طرح اس کو پار کر لو گے اور تعاقب سے اور ڈوبنے سے نہ ڈرو گے.پھر فرعون نے اپنے لشکروں سمیت بنی اسرائیل کا تعاقب کیا.لیکن سمندر کا ریلا کچھ ایسا آیا کہ وہ غرق ہو گئے اور فرعون نے یوں اپنی قوم کو تباہی میں ڈالا اور بچ نہ سکا.قرآن کریم کی آیات کے پیش نظر واقعہ کی کیفیت اِن آیات کو ملا کر قرآن کریم کے بیان کے مطابق واقعہ کی کیفیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل ارض مقدس کے ارادہ سے چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ پہنچا.اسے دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرائے اور سمجھے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے لیکن خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ؑ کی معرفت ان کو تسلیّ دلائی اور حضر ت موسیٰ ؑ سے کہا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں.جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر میں ایک راستہ ہو گیا اور وہ اس میں سے آگے روانہ ہوئے.ان کے دونوں طرف پانی تھا جو ریت کے ٹیلوں کی مانند یعنی
Page 41
اونچا نظر آتا تھا.لشکرِ فرعون نے ان کا پیچھا کیا.مگر بنی اسرائیل کے صحیح سلامت پار ہونے پر پانی پھر لوٹا اور مصری غرق ہو گئے.اِس واقعہ کے سمجھنے کے لئے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق تمام معجزات اﷲ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کسی انسان کا ان میں دخل اور تصرف نہیں ہوتا.پس حضرت موسیٰ ؑ کا عصا اٹھانا اور سمندر پر مارنا صرف ایک نشانی کے لئے تھا.نہ اس لئے کہ حضرت موسیٰ ؑ کا یا عصا کا سمندر کے سمٹ جانے میں کوئی دخل تھا.اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے الفاظ سے ہرگز ثابت نہیں کہ سمندر کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور اس میں سے حضرت موسیٰ ؑ نکل گئے تھے بلکہ قرآن کریم میں اِس واقعہ کے متعلق دو لفظ استعمال کئے گئے ہیں.ایک فَرَقَ اور ایک اِنْفَلَقَ کا.جن کے معنے جدا ہو جانے کے ہیں.پس قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق اِس واقعہ کی یہی تفصیل ثابت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کے وقت سمندر جدا ہو گیا تھا.یعنی کنارہ سے ہٹ گیا تھا اور جو خشکی نکل آئی تھی اس میں سے بنی اسرائیل گزر گئے تھے.اور سمندر کے کناروں پر ایسا ہو جایا کرتا ہے.بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آمدہ واقعہ کی مثال نپولین کی لائف میں چنانچہ نپولین کی لائف میں لکھا ہے کہ جب وہ مصر پر حملہ آور ہوا تو وہ بھی اپنی فوج کے ایک حصہ سمیت بحیرہ احمر کے کنارہ کے پاس جزر کے وقت گزرا تھا.اور اس کے گزرتے گزرتے مدّ کا وقت آگیا اور وہ مشکل سے بچا.اس واقعہ میں معجزہ یہ تھا کہ اﷲ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایسے وقت میں سمندر کے سامنے پہنچایا جبکہ جزر کا وقت تھا.اور حضرت موسیٰ ؑ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اﷲ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت پانی گھٹنا شروع ہو گیا.لیکن فرعون کا لشکر جب سمندر میں داخل ہوا تو ایسی غیر معمولی روکیں اس کے راستہ میں پیدا ہو گئیں کہ اس کی فوج بہت سُست رفتار سے بنی اسرائیل کے پیچھے چلی.اور ابھی سمندر ہی میں تھی کہ مدّ آگئی اور دشمن غرق ہو گیا.سمندر دو ٹکڑوںمیں پھٹا نہ تھا بلکہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا چنانچہ اس خیال کی تائید قرآن کریم کے الفاظ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ( سورہ شعراء آیت ۶۴) بھی کرتے ہیں.جن کے یہ معنی ہیں کہ جب سمندر ہٹا تو ہر ایک ٹکڑا ایک اونچے ریت کے ٹیلہ کی طرح ہو گیا.اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن کریم کا یہ منشاء ہوتا کہ سمندر دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا تو کُلکا لفظ جو نکرہ مفرد پر آیا ہے کبھی استعمال نہ ہوتا.پس کُل کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس موقع پر سمندر پھٹا نہ تھا بلکہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا.اور جیسا کہ اُن سمندر وںمیں ہوتا ہے جن کے کناروں پر چھوٹے گڑھے پانیوں کے ہوتے ہیں.سمندر کے ہٹنے پر وہ پانی کے مواقع پانی سے بھرے رہتے ہیں.ایسا ہی اُس وقت ہوا.بنی اسرائیل
Page 42
کے ایک طرف سمندر تھا اور ایک طرف وہ چھوٹی چھوٹی جھیلیں جو سمندر کے کنارے پر واقع تھیں.اور جیسا کہ قاعدہ ہے درمیان میں گزرنے والوں کو وہ اٹھی ہوئی نظر آتی تھیں.چنانچہ بحیرہ احمر کے نقشہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کنارہ پر بہت سی جھیلیں ہیں جو پرانے زمانہ میں اَور بھی زیادہ تھیں.جیسا کہ پرانے نقشہ جات سے ثابت ہے.آیت وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ … الخ کے متعلق سابق مفسرین کے خیالات جو معنے اِس آیت کے میرے نزدیک ہیں انہیں لکھنے کے بعد مَیں سابق مفسّرین کے خیالات بھی لکھ دینے مناسب سمجھتا ہوں.سابق مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ ؑنے نیل کا دریا پار کیا تھا.اور اس معجزہ کے بارہ میں انکا مزید خیال یہ ہے کہ دریا بار ہ جگہ سے پھٹ گیا تھا.یہ استدلال وہ سورہ شعراء کی آیت فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ(الشعراء:۶۴) سے کرتے ہیں.ان بارہ ٹکڑوں سے اُن کے نزدیک یہ فائدہ تھا کہ بارہ قبائل الگ الگ گزر جائیں.اِس بارہ میں انہوں نے اس قدر زور دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دریا میں سے گزرنے لگے تو چونکہ ہردو فریق کے درمیان پانی کی دیوار حائل تھی.بنی اسرائیل نے دریا میں سے گزرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک دوسرے گروہ ہم کو نظر نہ آئیں گے ہم دریا میں سے نہ گزریں گے.آخر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور خدا تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ پانی کی دیوار میںسونٹا داخل کرو.انہوں نے اسی طرح کیا اور دیوار میں سوراخ ہو گیا.اور وہ سب ایک دوسرے کی آوازیں سننے لگے اور صورتیں دیکھنے لگے.(کشّاف زیر آیت ھذا و شعراء ۶۳) گویا پانی اس طرح بستہ ہو گیا تھا کہ اس میں قائم رہنے والا سوراخ ہو سکتا تھا.اور پھر موسیٰ کا سونٹا اس قدر لمبا ہو گیا کہ وہ بارہ سڑکیں جس پر یہود کے بارہ قبیلے گزر رہے تھے.اُن سب کو ایک ہی وار میں وہ سونٹا چِیر گیا.اور سب میں ایک ہی وقت میں سوراخ کر گیا.اِس سوال پر کسی مفسر نے روشنی نہیں ڈالی کہ جن بنی اسرائیل میں اِس قدر محبت تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہ پاتے تھے اور ایک دوسرے کے متعلق تسلی پائے بغیر موسیٰ جیسے نبی کے ساتھ بھی دریا پار ہونے کے لئے تیار نہ تھے.اُن کے لئے بارہ راستے الگ الگ کیوں بنائے گئے تھے؟وہ ایک ہی راستہ پر سے سب کے سب کیوں نہ گزر سکتے تھے؟ جس پانی سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزرے وہ نیل کا پانی نہیں تھا اصل بات یہ ہے کہ مفسرین ایک خطرناک غلطی میں مبتلا ہوئے ہیں کہ وہ اس پانی کو جس میں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گزرے تھے نیل کا پانی سمجھتے ہیں لیکن یہ امر واقعات سے درست ثابت نہیں ہوتا.تاریخ اور آثار قدیمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جیسا کہ آج کل بھی ہے.صدر مقام کی آبادی نِیل کے مشرق کی
Page 43
طرف تھی.نہ کہ مغرب کی طرف.ایک مختصر نقشہ اس وقت کی آبادی کا نیچے دیا جاتا ہے.اِس نقشہ سے اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کنعان جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گئی تھی نیل کے شمال مشرق کی طرف ہے اور جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے.فراعنہ کے وقت میں اُن کا صدر مقام گوشن کے علاقہ میں تھا جسے وادی ثمیلات بھی کہتے ہیں.(انسا ئیکلوپیڈیا ببلیکا زیر لفظ رعمسیس) اور یہ وادی دریائے نیل کے مشرق میں ہے اور اِس جگہ سے جو شخص کنعان کو جائے اسے دریائے نیل سے گزرنا ہی نہیں پڑتا نیل اس کے مغرب میں رہ جاتا ہے.پس اِس آیت میں دریائے نیل کے گزرنے کا ذکر نہیں بلکہ کسی دوسرے پانی سے گزرنے کا سوال ہے.اور چونکہ اِس مقام سے لے کر قادس تک جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوئی دریا واقع نہیں (جیسا کہ نقشہ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے)
Page 44
جہاں سے حضرت موسیٰ مع ساتھیوں کے گزرے تھے وہ سمندر یا اس کا کوئی بڑھا ہوا حصہ تھا اِس لئے وہ جگہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی بہر حال سمندر یا اس کا کوئی بڑھا ہوا حصہ تھا.پس یہ معنی کہ ایک بہتا ہوا دریا عصائے موسیٰ کی ضرب سے رک گیا تھا اور اس کے ایک طرف کا پانی ایک طرف یخ ہو کر رہ گیا تھا اور دوسری طرف کا پانی دوسری طرف یخ ہو کر رہ گیا تھا اور اس میں سونٹا مار کر سوراخ کر دیا گیا تھا.یہ سب لغو قصے ہیں.قرآن کریم ان کی تصدیق نہیں کرتا.قرآن کریم بَحر اور یَمّ کا لفظ بولتا ہے جو گو دریا کے لئے بھی بول لیا جاتا ہے.لیکن اس کا استعمال سمندر یانمکین پانی کی جھیل کے لئے زیادہ تر ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے رہنے کے مقام اور کنعان کے درمیان سمندر یا اس کے ٹکڑے ہی آتے ہیں.بہنے والا دریا کوئی نہیں آتا.پس جس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے وہ سمندر یا اس کا کوئی بڑھا ہوا ٹکڑا تھا.حضرت موسیٰ ؑایسے وقت میں سمندر سے گزرے جبکہ جزر کا وقت تھا مَیں اوپر بتا آیا ہوں کہ سمندر میں مدّو جزر پیدا ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت میں پانی کنارے پر سے بہت دور پیچھے ہٹ جاتا ہے.اور دوسرے وقتوں میں وہ خشکی پر اور آگے آ جاتا ہے.سمندر پھاڑنے کے واقعہ کا اِسی مدّ و جزر کی کیفیت سے تعلق ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں سمندر سے گزرے جبکہ جزر کا وقت تھا اور سمندر پیچھے ہٹا ہوا تھا.اس کے بعد فرعون پہنچا.وہ بوجہ اس کے کہ کم سے کم ایک دن بعد حضرت موسیٰ ؑ کے چلا تھا وہ مارا مارکرتا ہوا جس وقت سمندر پرپہنچا ہے اُس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس خشک ٹکڑے کا جس سے وہ گزر رہے تھے.اکثر حصہ طے کر چکے تھے.فرعون کی غرقابی کی وقت سمندر کی مدّ کی حالت تھی فرعون نے ان کو پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے اس میں اپنی رتھیںڈال دیں.مگر سمندر کی ریت جو گیلی تھی اس کی رتھوں کے لئے مہلک ثابت ہوئی اور اس کی رتھیں اس میں پھنسنے لگیں اور اس قدر دیر ہو گئی کہ مدّ کا وقت آ گیا اور پانی بڑھنے لگا.اب اس کے لئے دونو ں باتیں مشکل تھیں.نہ وہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ پیچھے.نتیجہ یہ ہوا کہ سمندر نے اسے درمیان میں آ لیا.اور وہ اور اس کے بہت سے ساتھی سمندر میں غرق ہو گئے.اور چونکہ مدّ کا وقت تھا سمندر کا پانی جو کنارے کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے ان کی لاشوں کو خشکی کی طرف لا پھینکا.اس سوال کا جواب کہ فرعون نے بنی اسرائیل کا تعاقب خشکی کے راستہ سے ہو کر کیوں نہ کیا؟ اِس امر کا جواب کہ اگر صرف مدّ و جزر سے فائدہ اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تھے تو اس میں معجزہ کیا ہوا اوپر گزر چکا ہے.
Page 45
اِس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فرعون اوپر کی طرف سے ہو کر خشکی کے راستہ نہ گیا اور کیوں اس نے سمندر کی خشک جگہ میں سے ہو کر بنی اسرائیل کا تعاقب کیا؟ اِس کا جواب یہ ہے کہ سمندر کے اس مقام کے پاس جو غالباً سویز شہر کے پاس تھا ( یہاں سمندر کی چوڑائی صرف ۳؍ ۲ میل ہے.دیکھو انسائیکلو پیڈیا ببلیکازیر لفظ Exodus).بہت سی جھیلیں ہیں اور دلدلیں بھی ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جیسا کہ بائبل سے ثابت ہے.پہلے اوپر کی طرف گئے تھے مگر آگے جھیلوں کو راستہ میں دیکھ کر اور راستہ بند پا کر واپس سمندر کی طرف لَوٹے.بائبل میں لکھا.’’خدا نے انہیں یہ رہبری نہ کی کہ وہ فلسطیون کی راہ سے جاویں اگرچہ وہ نزدیک کی راہ تھی.کیونکہ خدا نے کہا.ایسا نہ ہو کہ وہ لڑائی دیکھ کے پچھتاویںاور مصر کو پھر جاویں.بلکہ خدا نے ان لوگوں کو دریائے قلزم کے بیابان کی طرف پھیرا‘‘.(خروج باب۱۳ آیت ۱۷،۱۸)اگر فرعون اوپر جاتا تو اسے اَور بھی چکر کاٹ کر جھیلوں کے اوپر سے ہو کر جانا پڑتا اور یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام اُس وقت تک بہت دور نکل چکے ہوتے.اور اس کی مملکت سے باہر چلے گئے ہوتے.اس لئے اس نے ان کے پکڑنے کی ایک ہی صورت ممکن دیکھی کہ وہ سمندر کے خشک شدہ حصہ میں سے ان کا تعاقب کرے.مگر اﷲتعالیٰ نے اس کی رتھوں کے بیلوں کو ڈرایا اور رتھوں کے راستہ میں مشکلات پیدا کر دیں جس کی وجہ سے اس کے سفر میں دیر ہوتی گئی اور مدّ کا وقت آ گیا.(حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اِس سفر کے لئے دیکھو خروج باب۱۳ آیت ۱۷ سے آخر تک اور پھر باب۱۴.اِس بیان میں بہت سی غلطیاں اور مبالغہ ہے مگر اجمالی طور پر اس سفر کا نقشہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے).جدید مؤرخین میں بنی اسرائیل کے گزرنے کے مقام میں اختلاف جدید مؤرخین میں یہ بحث ہے کہ بنی اسرائیل کے گزرنے کا واقعہ صحیح ہے تو اس کا مقام کون سا ہے؟ بائبل میں چونکہ ایک دریا کا بھی ذکر آتا ہے.بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام جھیل تمساح کے پاس سے گزرے ہیں.جس کا پانی ان کے نزدیک گزشتہ زمانہ میں ایک نالہ کے ذریعہ سے سمندر سے ملتا تھا.(ڈوبائے آمی سِٹیکل اور کنوُبل کی بھی یہی رائے ہے (دیکھو انسائیکلوپیڈیا ببلیکا اکسوڈس Exodus( خروج ) کالم ۱۴۳۸،۱۴۳۹.اور مقام کے لئے دیکھو اوپر کا نقشہ).بعض کے نزدیک وہ بحیرہ قلزم کے پاس سے نہیں گزرے بلکہ زُوآن کے پاس سے ہوتے ہوئے (دیکھو اوپر کا نقشہ) بحیرۂ روم کے پاس سے گزرے ہیں.(بقول شلائیڈن اور برگش انسا ئیکلو پیڈیا ببلیکا زیر لفظ Exodus) بعض کے نزدیک وہ ان علاقوں میں سے کسی علاقہ میں سے بھی نہیں گزرے بلکہ وہ شمالی افریقی مصر میں رہتے ہی نہ
Page 46
تھے بلکہ وہ اُس مصر میں رہتے تھے جو شمالی عرب میں واقع تھا اور ان کے نزدیک مُصر سے غلطی کھا کر بنی اسرائیل نے بائبل میں مِصر لکھدیا.(انسا ئیکلوپیڈیاببلیکا زیر لفظ Exodus) اِس تھیوری کے مطابق اگر سمندر کے عبور کرنے کا واقعہ صحیح تسلیم کیا جائے تو بنی اسرائیل مغرب سے مشرق کو نہیں بلکہ مشرق سے مغرب کی طرف گئے تھے اور خلیج سویز نہیں بلکہ خلیج عقبہ کو.سویز کے پاس سے نہیں بلکہ عقبہ کے پاس سے انہوں نے عبور کیا تھا.اگر عربی مصر کا جائے وقوع اس مقام سے اوپر سمجھا جائے تو پھر سمندر عبور کرنے کا واقعہ ان لوگوں کے نزدیک سراسر فرضی قرار پائے گا.آثارقدیمہ سے مصرنامی علاقہ کاشمالی افریقہ، شمالی شام اورشمالی عرب میں پائے جانے کا ثبوت اور مغر بی مصنفوں کے لئے تعیینِ مقام ، عبور میں مشکل اور اس کا حل آثار قدیمہ کی تحقیق اور پرانی تاریخوں سے یہ امر پوری طرح ثابت ہو چکا ہے کہ مصر نامی علاقہ بہ تغیر اشکال شمالی افریقہ.شمالی شام اور شمالی عرب میں پایا جاتا تھا.بلکہ ان تین علاقوں کے علاوہ اَور مقامات بھی مصر یا مصران یا مصرام یا مصرائیم یا مُصْری کہلاتے تھے.اور اسی وجہ سے بائبل کی بیان کردہ تفصیلات میں سے بعض کو شمالی افریقہ کے ملک مصر پر منطبق نہ دیکھتے ہوئے بائبل کے علوم کے جدید محققین میں سے بعض نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ افریقوی مصر نہیں بلکہ اگر یہ واقعات گزرے ہیں تو عربی مصر میں گزرے ہیں.موسیٰ علیہ السلام کے مدائن جانے کو وہ اس کی دلیل قرار دیتے ہیں کیونکہ مدائن شمالی عرب کے مصر کے ساتھ ملتا تھا.یہ امر کہ کئی علاقے مصر کہلاتے تھے مغربی مصنفوں کے لئے حیرت انگیز ہے لیکن عربی دانوں کے لئے نہیں.مصر کے معنے عربی زبان میں شہر کے ہیں جن لوگوں کو کسی بڑے شہر کے پاس رہنے کا یا وہاں جانے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ بڑے شہروں کے ارد گرد کے علاقے بعض دفعہ بیسیوں میل تک اپنے علاقہ کے شہر کا نام لے کر نہیں بلاتے بلکہ صرف شہر کہتے ہیں.لاہور کے ارد گرد کے دیہات میں جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص شہر گیا ہے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ لاہور گیا ہے.انگریزی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلستان میں بھی cityیعنی شہر کے لفظ سے انگلینڈ کے باشندے لندن مراد لیتے ہیں.پس عرب لوگ اور عربی سے ملتی جلتی زبانیں بولنے والے اُس زمانہ میں کہ جب بڑے شہروں کا رواج کم تھا.اگر کسی بڑے بڑے قصبات پر مشتمل علاقہ کو مصر کہتے تھے.خواہ وہ شام میں ہو خواہ عرب میں خواہ افریقہ میں تو اس میں تعجب کی کونسی بات ہے.مُصْری یا مصرام یا مصران یا مصرائیم سے ان کی مراد صرف یہ ہوتی کہ وہ شہروں والا علاقہ ہے.عرب جیسی صحرا نور د قوم کے لئے شہروں میں بسنا ایک عجوبہ
Page 47
سے کم نہ تھا.اور جس علاقہ میں کثرت سے بڑے بڑے شہر اور قصبات ہوں وہ ان کے لئے ایسا حیرت انگیز امر تھا کہ اس علاقہ کا نام شہری ملک رکھ دینا ان کے لئے ایک طبعی امر تھا.پس صرف مصر کے لفظ سے بنی اسرائیل کے جلاوطنی کے واقعات کو افریقی مصر کے علاقہ سے بد لا نہیں جا سکتا.راستہ کی جزئیات میں مشکلات کی وجہ سے اس اصولی سوال کو نظر انداز اکر دینا کہ بائبل اور قرآن کریم دونوں کے نزدیک اِس مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے اور قرآن کریم کے اس بیان کی روشنی میں کہ اس مصر میں مُردوں کی لاشوں کو دیر تک قائم رکھنے کا رواج تھا.ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی شخص کی شناخت کو اس لئے مشتبہ کر دیا جائے کہ گو اس کا حُلیہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام تو مذکورہ علامات کے مطابق ہے لیکن اس کے رومال کا رنگ وہ نہیں جو بتایا گیا تھا.پرانے زمانہ کے حالات اس طرح محفوظ نہیں کہ ہم اُس زمانہ کے حالات کو سو فیصدی درست معلوم کر سکیں.پس ہمیں ستّر فیصدی اتفاق کو مشعلِ راہ سمجھتے ہوئے تیس فیصدی اختلاف کو نظر انداز کر دینا چاہیے.اور تیس فیصدی اختلاف پر ستر فیصدی اتفاق کو قربان کر دینے کی حماقت سے بچنا چاہیے.بنی اسرائیل کے متعلق بعض لوگوں کا خیال کہ وہ مصر کی طرف نہیں گئے اور اس کے تین دلائل.بعض لوگ تاریخ کی منفی یا مثبت شہادت سے اس امر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر کی طرف نہیں گئے.ان کے استدلال کی وجوہ یہ ہیں:.(۱) مصری آثارِ قدیمہ میں بنی اسرائیل کا کہیں ذکر نہیں ملتا.(اسرائیل مصنّفہ اڈولف لاڈز صفحہ ۱۶۷) (۲) مِنْفَتَاح جس کے زمانہ میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ ؑبنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے.اس کے زمانہ کے ایک پرانے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حکومت کے پانچویں سال میں بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کنعان میں بس رہے تھے.اور بائبل بتا رہی ہے کہ بنی اسرائیل اس کے زمانہ میں وہاں سے نکلے اور کوئی ۵۰ سال میں جا کر کنعان میں داخل ہوئے.(۳) بیشک مصر میں بعض ایشیائی قبائل کے ورود کا پتہ ملتا ہے.لیکن ان واقعات کو اگر بنی اسرائیل پر چسپاں کیا جائے تو کبھی واقعات ملتے جلتے ہیں مگر تاریخیں ٹھیک نہیں بیٹھتیں.اور کبھی تاریخیں ٹھیک بیٹھتی ہیں تو واقعات مطابقت نہیں کھاتے پس معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب بناوٹی کہانی ہے.بنی اسرائیل کے مصر کی طرف نہ جانے کے دلائل کا ردّ چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے مصر میں جانے اور وہاں سے آنے کا ذکر کرتا ہے.ہم اس اعتراض کی طرف توجہ کرنے پر مجبور ہیں.اور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ (۱) یہ ضروری نہیں کہ ہر امر کا آثارِ قدیمہ سے حال معلوم ہو جائے.کیا اگر آج تہذیب کی ترقی کے زمانہ میں کسی
Page 48
متمدن ملک کی تاریخ کو مٹا دیا جائے تو کیا اس کی پوری تاریخ اس کے آثار سے معلوم ہو سکے گی.کیا مثلاً انگلستان یا یونائیٹڈسٹیٹس امریکہ یا جرمنی یا فرانس کی مکمل تاریخ تمام قوموں کے اعداد و شمار، مذاہب اور ان کے فرقوں کا حال اور ان کے علوم و فنون کا پورا پتہ کسی ایک یا دو شہروں کے نشانات سے لگایا جا سکتا ہے.اگر موجودہ زمانہ کے صحیح حالات مکمل طور پر موجودہ زمانہ کے آثار سے بھی معلوم نہیں ہو سکتے تو اس سے زیادہ غیر معقول خیال کیا ہو گا کہ گزشتہ زمانہ کے تفصیلی حالات چند ہزار سال پہلے کے دو یا چار قصبات کے کھودنے سے معلوم ہو سکیں گے.یہ تو ایسی خلافِ عقل بات ہے کہ اس پر کسی علم کی بنیاد رکھنی علم سے تمسخر کرنا ہے.مثبت شہادت توخیر کچھ قیمت بھی رکھتی ہے.گو اس میں بھی بہت سی غلطیوں کا امکان ہے مگر یہ کہنا کہ چونکہ فلاں قوم کا ذکر نہیں ملا اس لئے وہ وہاں نہ تھی.ایسا خلاف عقل خیال ہے کہ اسے علمی کتب میں پیش کرنے سے مصنّفین کو خود ہی رکنا چاہیے تھا.آخر بنی اسرائیل کی مصر میں حیثیت کیا تھی.غلاموں کی طرح وہ رہتے تھے.کوئی ایسے بڑے کام ان کے سپرد نہ تھے کہ ان کا ذکر تاریخی آثار میں آتا.ان کی اہمیت کا باعث غالباً صرف یہ تھا کہ وہ ایک منفرد مذہب رکھتے تھے.اور یا یہ کہ غالباً ان کے زمانہ کے مصری بادشاہ خالص مصری قوم سے نہ تھے اور وہ بنی اسرائیل سے ڈرتے تھے کہ یہ کسی دوسری قوم سے مل کر ہماری حکومت کو نقصان نہ پہنچائیں.ان حالات میں آثارِ قدیمہ میں اُن کے نام آنے کی ضرورت ہی نہیں معلوم ہوتی.اور اگر نام آتا بھی تو آثار قدیمہ سے صرف تاریخی ٹکڑے معلوم ہو سکتے ہیں پوری تاریخ معلوم نہیں ہو سکتی کہ ان کی خاموشی کوئی دلیل سمجھی جائے.دوسری دلیل کہ کسی فرعونی اثر سے معلوم ہوتا ہے جو غالباً مِنْفَتَاح فرعونِ مصر کا اثر ہے یا اِس سے پہلے کے کسی بادشاہ کا کہ اس زمانہ میں بنی اسرائیل کنعان میں بستے تھے کوئی قابل توجہ جرح نہیں کیونکہ اگر یہ اثر جس کی تاریخ معین نہیں حضرت یوسفؑ کے بعد کے زمانہ کا ہےاور خروج موسیٰ ؑسے پہلے کا ہے.تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کچھ حصہ خروج موسیٰ ؑ سے پہلے بھی کنعان کی طرف روانہ ہو گیا تھا.اور اگر یہ اثر یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے کا ہے یا ہجرت موسوی کے بعد کا.تو اس سے کوئی خلاف نتیجہ نکلتا ہی نہیں.تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ بیشک بعض ایشیائی اقوام کا مصر میں ورود تاریخوں سے ملتا ہے مگر انہیں بنی اسرائیل سمجھنے کی کوئی وجہ نہیں.ایک خالص منفی دلیل ہے.اور منفی دلیل ناقص آثار کی بناء پر کوئی بھی دلیل نہیں.ایک کتاب جس کے آدھے ورق پھٹے ہوئے ہوں.ان کی بناء پر کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں مضمون اِس کتاب میں نہیں کیونکہ وہ اِن ورقوں میں نہیں جو میرے پاس ہیں.
Page 49
بنی اسرائیل کے مصر میں ورود کے چار قیاسی دلائل ان تینوں قسم کے دلائل کو ردّ کرنے کے بعد مَیں بعض قیاسی دلائل اس امر کی تائید میں دیتا ہوں جو بنی اسرئیل کے مصر میں ورود کے ثبوت میں ہیں.(۱) یہی لوگ جو بنی اسرئیل کے مصر سے آنے کے خلاف ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ موسیٰ کا نام خود مصری زبان میں ہے.ان کے نزدیک مُو سیٰ ؑ مَوْسِے تھا.جس کے معنے ’’بیٹے ‘ ‘کے ہیں.( مَوْزِزْ اینڈ مَا نَوتھِیْ اِزم.مصنفہ سِگمْنَڈ فَرائڈ SIGMUND FREUD زیر عنوان Moses and Egyptian) اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہے تو پھر یہ اس امر کا ثبوت بھی ہے کہ اسرائیلی افریقی مصر میں تھے.اور وہاں ان کی رہائش اِس قدر لمبی تھی کہ انہوں نے مصری زبان کے نام بھی رکھنے شروع کر دئے تھے.یہ لوگ اِس امر کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ؑ کے بعض دوسرے ساتھیوں کے نام حور وغیرہ بھی جو بائبل میں آتے ہیں مصری ہیں.اگر یہ درست ہے تو بنی اسرائیل کے مصر میں رہنے اور وہاں سے نکلنے کا یہ مزید ثبوت ہے.(۲) بائبل مصر میں اپنے باپ دادوں کو بادشاہ اور حاکم قرار نہیں دیتی.کہ سمجھا جائےانہوں نے اپنی شان بڑھانے کے لئے یہ قصہ گھڑ لیا.بائبل تو ان کو وہاں غلاموں کی صورت میں پیش کرتی ہے.اور اِس قسم کے قصہ بنانے کا کوئی محرک نظر نہیں آتا.پس اسے بناوٹی قرار دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں.(۳) بائبل میں جو تفصیلات ہیں وہ سب افریقوی مصر پر صادق آتی ہیں.فراعنہ کا ذکر ان کے بعض بادشاہوں کے نام جو تاریخ سے ثابت ہو گئے ہیں.افریقوی مصر کے بعض شہروں کا نام جو گو مٹ چکے تھے مگر اب پرانی جگہوں کی کھدائیوں سے ان کی تصدیق ہو گئی ہے.فرعونیوں کے قوانین اور آداب کے متعلق جو بائبل میں روشنی ڈالی گئی ہے.سب تفصیلات آثار قدیمہ سے سچی ثابت ہو رہی ہیں.اسی طرح مثلاً یہ کہ انہوں نے غلّہ کے لئے خاص گودام مقرر کر چھوڑے تھے.پرانے آثار سے ایسے کئی گوداموں کا پتہ چلا ہے.( ضمناً یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآنِ کریم نے مصریوں کے مذہب کے متعلق بھی روشنی ڈالی ہے کہ وہ بادشاہ میں خدا کی صفات تسلیم کرتے تھے.اور یہ امر بھی آثارِقدیمہ سے ثابت ہو گیا ہے) اسی طرح مصر کے جغرافیہ کے متعلق بائبل کی معلومات بہت حد تک درست ہیں.پس یہ سب غالب طور پر درست تفصیلات جو بعض ایسے امور کے متعلق ہیں جو امتدادِ زمانہ کی وجہ سے مخفی ہو گئے تھے.اور اب آثارِ قدیمہ سے ان کا پتہ چلا ہے.بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کا گہرا تعلق اس زمانہ کے مصر کے ساتھ تھا اور جو شبہات اب پیدا کئے جا رہے ہیں محض اِس وجہ سے ہیں کہ کیوں سو فیصدی تطابق انہیں ان واقعات سے نہیں جو نامکمل آثارِ قدیمہ سے یا نامکمل تاریخوں سے ان معترضین کو معلوم ہوئے ہیں.اور یہ
Page 50
مطالبہ خلافِ عقل ہے.(۴) قدیم یونانی تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کے لوگ بھی اس امر کو تسلیم کرتے تھے کہ اسرائیلی وہاں سے نکل کر گئے ہیں گو وہ روایات بے سرو پا ہیں.مثلاً ان میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی مصر کے کوڑہیوں کی اولاد ہیں.اور چونکہ ان کو دوسروں سے الگ رکھا گیا.اور چونکہ وہ مصری خداؤں کا انکار کرنے لگے تھے.انہوں نے بغاوت کی اور اس لئے انہیں وہاں سے نکالا گیا.(یہ روایات علاوہ اور مصنفوں کی اَبد ِ یْرَا کے ہیْکَاتِیَسْ نے جو سکندر رومی کا ہم عصر تھا اور منیتھو نے جو باشندہ ہِلْیُو پول کا تھا لکھی ہیں.( دیکھو اسرائیل مصنفہ اڈولف لاڈز صفحہ ۱۶۷.۱۶۸) اِس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روایات بائبل کی روایات کے کلی طور پر خلاف ہیں.لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بنی اسرائیل مصر میں نہ گئے تھے اور نہ وہاں سے نکلے تھے تو پھر یہ روایات مصر والوں نے بنائیں کیوں؟ روایات میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ تو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مصری اسرائیلیوں کے دشمن تھے.ان کا بادشاہ موسیٰ ؑ کے مقابلہ میں ذلیل ہو کر مرا.اس لئے انہوں نے یہ روایات گھڑ لیں کہ یہ کوڑ ہی تھے اور ہم نے ان کومار کر نکال دیا.لیکن اس کی غرض کیا ہو سکتی تھی کہ نہ اسرائیلی ان کے ملک میں آئے نہ وہاں سے نکلے مگر مصری خود بخود قصے بنانے لگ گئے کہ اسرائیلی ہمارے ملک میں آئے تھے اور ہم نے ان کو نکال دیا.اور اِدھر خود اسرائیلیوں نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہم وہاں گئے تھے اور انہوں نے ہمیں نکال دیا.یہ بات بالکل خلافِ عقل ہے اور بائبل اور قرآن کریم کا بیان کہ بنی اسرائیل مصر گئے تھے اور وہاں سے خدا تعالیٰ کی مدد سے نکلے بالکل درست ہے.بنی اسرائیل کے سمندر سے گزرنے کے مقام کی تفصیل اِ س امر کے واضح ہو جانے کے بعد کہ مصر سے مراد افریقی مصر ہی تھا یہ تو یقین ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل افریقی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے تھے.اب رہا یہ سوال کہ وہ شمال کی طرف سے گئے یا وسط سے یا جنوب سے.مذہبی نقطۂ نگاہ سے کوئی بڑی اہمیت نہیں رکھتا.مگر جہاںتک معلومہ تحقیق کا تعلق ہے اور بائبل اور قرآنِ کریم کی بتائی ہوئی مدّ و جزر کی کیفیات سے نتیجہ نکلتا ہے یہی بات قرین قیاس ہے کہ بنو اسرائیل تَل ابی سلیمان کے مقام سے ( دیکھو نقشہ اس جگہ فرعونِ موسیٰ کا پایہ تخت ہوتا تھا) پہلے وسط یعنی جھیل تمساح کی طرف گئے جہاں سے کنعان نزدیک پڑتا ہے ( دیکھو نقشہ ) پھر وہاں سے جھیلوں کی روک دیکھ کر جنوب کی طرف لَوٹے.اور سویز کے مقام کے پاس سے سمندر میں سے جزر کے وقت پار ہوئے اور وہاں سے قادس کی طرف روانہ ہو گئے.جہاں سے بنی اسرائیل سمندرپار ہوئے وہاں کا فاصلہ صرف ۲،۳میل تھا وَ اَغْرَقْنَاۤ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَ
Page 51
َنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ سے بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کیا تھا وہ بہت چھوٹا علاقہ تھا.کیونکہ اگر وہ لمبا علاقہ ہوتا تو ایک طرف کھڑے ہوئے درمیان میں ہونے والے واقعہ کو وہ دیکھ نہ سکتے تھے اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ خلیج سویز کے انتہائی شمالی حصہ کا پھیلاؤ کل ۲،۳ میل ہے.اگر اس کے نصف میں فرعون کی غرقابی کا مقام تصوّر کیا جائے تو صرف چھ سات سَو گز پر بنی اسرائیل کھڑے تھے اور ان کی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے.معلوم ہوتا ہے فرعون اور اس کے کچھ ساتھی تیرنا نہ جانتے تھے.یا یہ کہ شام کا وقت تھا جلد ہی اندھیرا ہو گیا اور وہ راستہ بھول کر کھلے سمندر کی طرف بڑھنے لگ گئے اور اس میں غرق ہو گئے.نپولین کے محولہ بالا واقعہ میں بھی اسی طرح ہوا تھا.شام کا وقت قریب تھا.جب وہ اور اس کے ساتھی سمندر کے خشک شدہ حصہ میں داخل ہوئے.ابھی پھر ہی رہے تھے کہ مدّ کا وقت آ گیا.اور چونکہ خشکی کی طرف جھیلیں تھیں.سمندر کا پانی جھیلوں کے پانی سے مل گیا اور جہت کا اچھی طرح معلوم کرنا مشکل ہو گیا اور اس امر کا خوف پیدا ہو گیا کہ بجائے کنارے کی طرف جانے کے نپولین اور اس کے ہمراہی گہرے سمندر میں جا کر غرق ہو جائیں.اس پر نپولین نے اپنے ہمراہیوں کو اِس + شکل پر چلنے کا حکم دیا.جس طرف کے آدمی پانی گہرا پاتے وہ اس طرف سمٹ آتے تھے جدہر کے لوگ پانی تھوڑا بتاتے تھے اور پھر نئی جگہ پر یہی شکل بنا لیتے تھے اِسی طرح کرتے کرتے آخر انہیں کنارہ مل گیا.نپولین ریت پر آکر لیٹ گیا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ اگر آج میں غرق ہو جاتا تو ساری عیسائی دنیا شور مچا دیتی کہ یہ بھی ایک فرعون تھا جو سمندر میں غرق ہو گیا.وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰۤى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ ؑسے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے چلے جانے کے بعد الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ۰۰۵۲ ظلم سے کام لیتے ہوئے بچھڑے کو( معبود) بنا لیا.حَلّ لُغَات.ظٰلِمُوْنَ.ظَلَمَ سے اسم فاعل ظَالِمٌ آتا ہے.اَلظّٰلِمُوْنَ اور اَلظَّالِمِیْنَ اس کی جمع ہیں.ظَلَمَ فُـلَانٌ ظُلْمًا وَظَلْمًا کے معنے ہیں وَضَعَ الشَّیْءَ فِیْ غَیْرِ مَوْضِعِہٖ کسی چیز کا بے محل اور بے موقع استعمال کیا نیز ظَلَمَ فُـلَانًا کے معنے ہیں فَعَلَ لَہُ الظُّلْمَ اس پر ظلم کیا.ظَلَمَ فُـلَانٌ حَقَّہٗ: نَقَصَہٗ اِیَّاہُ اُس کو
Page 52
اُس کا حق پورا نہ دیا (اقرب) نیز حد سے بڑھ جانے اور دوسرے کی ملکیت پر دست درازی کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں.(اقرب) مفردات میں ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں (۱) ظُلْمٌ بَیْنَ الْاِنْسَانِ وَ بَیْنَ اللّٰہِ تَعَالٰی.اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ظلم.یعنی جو حقوق اللہ تعالیٰ کے بندے کے ذمہ ہیں وہ اس کو دینے کی بجائے دوسروں کو دیئے جائیں وَ اَعْظَمُہُ الْکُفْرُ وَالشِّرْکُ وَ النِّفَاقُ اوران معنوں کے لحاظ سے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا جائے.اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے اور نفاق سے کام لیا جائے حالانکہ مناسب تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو مانا جائے اور اس کی توحید کا اقرار کیا جائے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہےاِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ (لقمان:۱۴) کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے (۲) ظُلْمٌ بَیْنَہٗ وَ بَیْنَ النَّاسِ لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا.(۳) ظُلْمٌ بَیْنَہٗ وَ بَیْنَ نَفْسِہٖ انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا چنانچہ آیتفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ (فاطر:۳۳) میں یہی ظلم مراد ہے.(مفردات) پس ظالم کے معنے ہوں گے (۱) بے محل و بے موقع کام کرنے والا.(۲) کسی کے حق کو کم دینے والا.(۳) حد سے بڑھ جانے اور دوسرے کی ملکیت پر دست درازی کرنے والا.(۴) شرک کرنے والا.(۵) ظلم کرنے والا.تفسیر.بنی اسرائیل اور بچھڑے کی پرستش کا واقعہ اِس آیت میں ایک اور احسان کا ذکر ہے جس کی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ناقدری کی اور احسان کو عذاب میں بدلنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی.یہ واقعہ اس طرح ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اﷲ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک پہاڑ پر جو اُن کے سفر کے راستہ میں تھا.کچھ دن الگ عبادت کریں اور خدا تعالیٰ کے خاص ارشادات سنیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام اِس حکم کے ماتحت پہاڑ پر گئے.بنی اسرائیل نے کچھ دنوں کے بعد محسوس کیا کہ انہیں دیر ہو گئی ہے اور سمجھے کہ موسیٰ ؑیا فوت ہو گئے ہیں یا کوئی اور ناگوارواقعہ ہوا ہے.اس پر انہوں نے ان زیورات سے جو ان کے پاس تھے ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور کہا یہ بچھڑا ان کا معبود ہے.اور اس کی پرستش میں لگ گئے.خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی اور واپس جانے کا حکم دیا.بائبل میں اِس واقعہ کا یوں ذکر آتا ہے.’’ اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ خداوند پاس چڑھ آ.تو اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں سے ستر شخص.تم دور سے سجدہ کرو اور موسیٰ اکیلا خداوند کے نزدیک آوے پر وَے نزدیک نہ آویں.اَور لوگ اس کے ساتھ نہ چڑھیں.‘‘ (خروج باب ۲۴ آیت ۱،۲).پھر لکھا ہے.اس پر عمل کرتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام
Page 53
نے اپنی قوم کے بزرگوں سے کہا.’’ تم ہمارے لئے یہاںجب تک کہ ہم تم پاس پھر آویںٹھیرو.اور دیکھو کہ ہارون اور حور تمہارے ساتھ ہیں.اگر کسی کو کچھ کام ہووے تو وہ ان کے پاس جاوے.‘‘ (باب ۲۴ آیت ۱۴) پھر لکھا ہے.’’ اور موسیٰ بدلی کے درمیان چلا گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا.اور موسیٰ پہاڑ پر چالیس دن رات رہا.‘‘ باب ۲۴ آیت ۱۸.بنی اسرائیل کے بچھڑا بنانے کا واقعہ بائبل میں پھر لکھا ہے.’’ جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ پہاڑ سے اترنے میں دیری کرتا ہے تو وَے ہارون کے پاس جمع ہوئے اور اسے کہا کہ اُٹھ ہمارے لئے معبود بنا کہ ہمارے آگے چلیں.کیونکہ یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک سے نکال لایا.ہم نہیں جانتے کہ اسے کیا ہوا.ہارون نے انہیں کہا کہ زیور سونے کے جو تمہاری جو رؤوں اور تمہارے بیٹوں کےاور تمہاری بیٹیوں کے کانوں میں ہیں توڑ توڑ کر مجھ پاس لاؤ.چنانچہ سب لوگ سونے کے زیور جو اُن کے کانوں میں تھے توڑ توڑ کر ہارون کے پاس لائے اور اس نے ان کے ہاتھوں سے لیا اور ایک بچھڑا ڈھال کر اس کی صورت حکاّکی کے ہتھیار سے درست کی اور انہوں نے کہا کہ اے اسرائیل یہ تمہارا معبود ہے جو تمہیں مصر کے ملک سے نکال لایا اور جب ہارون نے یہ دیکھا تو اس کے آگے ایک قربانگاہ بنائی اور ہارون نے یہ کہہ کے منادی کی کہ کل خداوند کے لئے عید ہے.اور وے صبح کو اُٹھے اور سو ختنی قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانیں.اور لوگ کھانے پینے کو بیٹھے اور کھیلنے کو اٹھے.‘‘ (خروج باب ۳۲ آیت ۱ تا ۶) اوپر کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل کے قول کے مطابق اﷲ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر کچھ دن بسر کرنے کی ہدایت کی.انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے بعد ہارون اور حور کی اطاعت کا حکم دیا.کچھ عرصہ کے بعد بنی اسرائیل نے خیال کیا کہ شاید موسیٰ مر گئے ہیں کہ واپس نہیں لَوٹے.اور ہارون نے کہا کہ ہمارے لئے کچھ بُت بناؤ.انہوں نے فوراً اس پر آمادگی ظاہر کی اور انہیںاپنے زیورات لانے کو کہا.جو وہ لے آئے.اور ان زیورات سے ہارون نے اُن کے لئے ایک بچھڑا بنایا.جس کے آگے ہارون کی مدد اور اعانت سے ان لوگوں نے قربانیاں گزرانیں.بنی اسرائیل کے بچھڑا بنانے کا ذکر قرآنِ مجید میں قرآن کریم میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے:.’’ اور ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور پھر ان تیس راتوں کو دس راتیں اور بڑھا کر مکمل کر دیا اِس طرح اس کے رب کا وعدہ چالیس راتوں کی صورت میں مکمل ہو گیا.‘‘ (الاعراف : ۱۴۳)
Page 55
بائبل کا یہ بیان ایسا خلاف عقل ہے کہ کوئی عقلمند اسے ایک منٹ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتا.اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کا ایک نبی جو خدا تعالیٰ کا کلام سننے کا عادی تھا وہ ایک بے جان.بے اثر.بیفائدہ مُورت بنا کر اسے خدا قرار دیتا ہے اور خود بھی اس کی عبادت کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اس کی عبادت کرواتا ہے.سوائے پادریوں اور یہودی راہبوں کے جو بائبل کی رطب و یا بس تحریرات کو ماننے کیلئے عقل کے کانوںمیں سیسہ ڈالے بیٹھے ہیں کون اس غیر معقول بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ دس دن کے اندر بچھڑا کس طرح بن گیا؟ بعض لوگ اِس واقعہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دس دن کے وقفہ کے اندر بچھڑا کیونکر بن گیا؟ ان کے اس اعتراض سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے وہ بچھڑا دیکھا ہے اور اس کی صنعت انہیں ایسی اعلیٰ معلوم ہوئی ہے کہ اُس کے بنانے کے لئے بڑے بڑے کارخانوں اور کامل الصناعت انجینئروں کی ضرورت تھی.سونے کو پگھلا کر مٹی کے ایک سانچے میں ڈال کر اس سے ایک بھدّا سا بُت بنا دینا کونسا بڑا کام ہے جس شخص نے وہ بُت بنایا تھا وہ دل سے مشرک تھا اور اِس کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح بنی اسرائیل میں پھرشرک جاری ہو جائے.پس اس نے گھنٹوںمحنت کر کے ایک بھدّا سا بُت بنا دیا تو اس میں کیا تعجب ہے؟ ایسے بُت کا بنانا سادہ کڑوں کے بنانے سے زیادہ مشکل نہیں جو چند گھنٹوں میں سُنار تیار کر لیتے ہیں.باقی رہا یہ سوال کہ ہارون ؑ کو یہ فن کہاں سے آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب یہودی یا عیسائی دیں.ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام اس مشرکانہ فعل سے بَری تھے.اس کا بنانے والا ایک اور شخص سامری نام تھا.ممکن ہے وہ خود سُنار ہو یا ممکن ہے اُس نے اپنے ہم خیال سُناروں کی مدد سے بچھڑا بنایا ہو.تیس راتوں کی بجائے چالیس راتوں کا وعدہ احسان تھا نہ کہ وعدہ خلافی بعض لوگ اعتراض کرتے کہ پہلے تیس راتوں کا وعدہ کرنا پھر چالیس راتیں کر دینا کیا وعدہ خلافی نہیں؟ یہ ایسا ہی اعتراض ہے.جیسے کسی کو تیس روپے دینے کا وعدہ کر کے چالیس دئے جائیں تو اسے وعدہ خلافی کہا جائے.خدا کا کلام ایک نعمت ہے.تیس رات کلام کی جگہ چالیس رات کلام کر کے نعمت کو مکمل کیا گیا ہے اور نعمت کی تکمیل وعدہ خلافی نہیں کہلاتی بلکہ انعام اور احسان کہلاتی ہے.
Page 56
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۰۰۵۳ پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر گذار بنو.حَلّ لُغَات.ثُمَّ.حرفِ عطف ہے جو ترتیب اور تراخی کے لئے آتا ہے یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ معطوف اپنے معطوف علیہ کے بعد ترتیبًا اور کچھ دیر کے بعد واقع ہوا ہے اُردو زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ’’پھر‘‘ ’’تب‘‘ ’’بعدازاں‘‘ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں.اور بعض اوقات ثُمَّکے آخر میں تا بھی لے آتے ہیں جیسے کہ اس شعر میں اسے لایا گیا ہے. وَلَقَدْ اَمُرُّ عَلَی اللَّئِیْمِ یَسُبُّنِیْ فَمَضَیْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لَا یَعْنِیْنِیْ (اقرب) یعنی میں جب کبھی گالیاں دینے والے ایک کمینے شخص کے پاس سے گزرتا ہوں.تو خاموشی سے گزر جاتا ہوں اور اپنے نفس میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے مخاطب نہیں کرتا.عَفَوْنَا: عَفٰـیسے متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے.اور عَفَـی عَنْہُ وَلَہٗ ذَنْبَہٗ وَ عَنْ ذَنْبِہٖ (یَعْفُوْ) کے معنے ہیں صَفَحَ عَنْہُ وَ تَرَکَ عُقُوْبَتَہٗ وَھُوَ یَسْتَحِقُّہَا وَ اَعْرَضَ عَنْ مُّؤَاخَذَتِہٖکہ اس کے قصور سے درگزر کیا اور اس کی سزا کو معاف کیا اور اس کی غلطی پر مؤاخذہ نہ کیا در آنحالیکہ وہ سزا کا مستحق تھا.جب عَفَی اللہُ عَنْ فُلَانٍ کا فقرہ کہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مَحٰی ذُنُوْبَہٗ اﷲ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو مٹا دیا.اور عَفَـٰی عَنِ الشَّیْ ءِ کے معنے ہیں اَمْسَکَ عَنْہُ وَ تَنَزَّہَ عَنْ طَلَبِہٖ کسی چیز سے رُکا رہا اور اس کی طلب سے اپنے آپ کو علیٰحدہ رکھا.( اقرب) پس عَفَوْنَا کے معنے ہوں گے کہ باوجود اس کے کہ تمہارا گناہ اس قابل تھا کہ ضرور سزا دی جاتی.لیکن پھر بھی ہم نے مواخذہ نہ کیا اور معاف کر دیا.(۲) ہم تم کو سزا دینے سے رُکے رہے.لَعَلَّ.لَعَلَّ حروف مشبّہ بالفعل میں سے ہے اس کے ساتھ یائِ متکلّم بھی لگائی جاتی ہے جیسے لَعَلِّیْ اور کبھی لَعَلَّاور یاء ِمتکلّم کے درمیان نون زائد کیا جاتا ہے جسے نونِ وقا یہ کہتے ہیں جیسے لَعَلَّنِیْ.نون کے بغیر استعمال زیادہ ہے یہ اسم کو نَصب اور خبر کو رَفع دیتا ہے جیسے لَعَلَّ زَیْدًا قَائِمٌ.لیکن فَرَّاء اور بعض دیگر نحویوں کے نزدیک اسم اور خبر دونوں کو نصب دیتا ہے جیسے لَعَلَّ زَیْدًا قَائِمًا.لَعَلَّکے کئی معنے ہیں (۱) پسندیدہ شَے کی توقع اور ناپسندیدہ شَے سے خوف ان معنوں میں یہ ایسے امر کے لئے
Page 57
استعمال ہوتا ہے جس کا حصول ممکن ہو گو مشکل ہو.قرآن کریم میں جو فرعون کاقول نقل ہے.لَعَلِّيْۤ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ(المؤمن: ۳۷‘ ۳۸) اس کے متعلق مفسّرین کہتے ہیں یہ اس کی جہالت پر دلالت کرتا ہے وہ اپنی نادانی سے یہی سمجھتا ہو گا کہ میں اونچے مکان پر سے خدا تک پہنچنے کا راستہ پا لوں گا مگر میرے نزدیک یہ درست نہیں.میرے نزدیک اس کی توجیہ یہ ہے کہ یا تو وہ یہ کہتا ہے کہ علم ہیئت کے ذریعہ سے موسیٰ کے مستقبل کو معلوم کر کے اس کا مقابلہ کروں گا اور یہ ُعقدہ گو باطل ہے مگر کثرت سے رائج ہے.یا پھر اس کا قول بطور تمسخر ہے.چونکہ موسیٰ ؑ بار بار خدا کو آسمان پر بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا اور فرشتے مجھ سے باتیں کرتے ہیں.اس پر وہ تمسخر سے کہتا ہے کہ لائو ایک مکان بنائو شائد اس طرح ہم موسیٰ کے خدا کو پہنچ جائیں اور ہم بھی اس سے باتیں کر کے دیکھیں.مطلب یہ کہ ایک طرف خدا کو آسمان پر ماننا اور دوسری طرف اس سے باتیں کرنے کا دعویٰ یہ خلافِ عقل ہے الٰہی علوم سے ناواقف انسانوں کے لئے اس مسئلہ کو نہ سمجھ سکنا قابلِ تعجب نہیں (۲) اس کے معنے محض تعلیل کے بھی ہوتے ہیں جیسےفَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى(طٰہٰ : ۴۵) یہی معنے ترجمہ میں استعمال کئے گئے ہیں (۳) کوفیوں کے نزدیک کبھی اس کے معنوںمیں استفہام کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے کلیات ابی البقاء میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ یعنیلَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ(الشعراء: ۱۳۰)کے سوا جہاں کہیں بھی لَعَلَّ استعمال ہوا ہے توقع کے معنوں میں نہیں بلکہ تعلیل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یعنی ’’تاکہ‘‘ یا ’’تا‘‘ کے معنوں میں (۴) کلام ِ ُملوک کے طو ر پر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی بادشاہ کے لئے کوئی اور یا بادشاہ اپنی نسبت خود امید اور توقع کے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن مراد اس سے یقینی بات یا حکم کے ہوتے ہیں.تَشْکُرُوْنَ.شَکَرَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور شَکَرَ کبھی بغیر صلہ اور کبھی ل کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے.یعنی شَکَرَہٗ اور شَکَرَلَہٗ ہر دو طرح استعمال کرتے ہیں.لیکن اگر شَکَرَ کا صلہ لام آئے تو یہ زیادہ فصیح سمجھا جاتا ہے.شَکَرَہٗ وَ شَکَرَلَہٗ کے معنے ہیں اَثْنٰی عَلَیْہِ بِمَا اَوْلَاہُ مِنَ الْمَعْرُوْفِ کسی کے احسان کے باعث اس کی تعریف کی.گویا محسن کی تعریف کے ساتھ اقرارِ احسان شکر کہلاتا ہے.(اقرب) تفسیر.خروج باب ۳۲ آیت۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بچھڑا بنایا تو اﷲ تعالیٰ کا غضب اُن پر بھڑک اٹھا اور اس نے موسیٰ سے کہا ’’ کہ مَیں اِس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک گردن کش قوم ہے اب تو مجھ کو چھوڑ کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور مَیں انہیں بھسم کروں.‘‘
Page 58
پھر آیت ۱۴ میں ہے.’’ اِس پر حضرت موسیٰ ؑنے ان کے لئے دعا کی اور مطابق توریت تب خداوندنے اس بدی سے، جو چاہا تھا، کہ اپنے لوگوں سے کرے پچھتایا.‘‘ یعنی انہیں سزا نہ دی بلکہ درگزر فرمایا.(آیت ۱۱.۱۴) عَفَوْنَا عَنْکُمْ سے مراد قومی سزا کی معافی ہے نہ کہ تمام قوم کی اِس جگہ عَفَوْنَا عَنْکُمْ سے مراد قومی سزا کی معافی ہے نہ کہ تمام قوم کی معافی.قومی جرائم کی دو شقیں ہوتی ہیں.ایک شق اُس کی تمام قوم سے بحیثیت مجموعی تعلق رکھتی ہے.اور ایک شق اس کے افراد سے تعلق رکھتی ہے.قومی جرائم میں کچھ اشخاص شرارت میں زیادہ حصہ لینے والے ہوتے ہیں.کچھ کم حصہ لینے والے ہوتے ہیں.کچھ لوگ حصہ تو نہیں لیتے مگر دل میں ساتھ ہوتے ہیں اور زبان سے بھی ساتھ دیتے ہیں.کچھ لوگ زبان سے تو ساتھ نہیں دیتے مگر دل سے ساتھ ہوتے ہیں.کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل میں بھی شامل ہو جاتے ہیں مگر دل میں مخالف ہوتے ہیں.صرف بُزدلی کی وجہ سے اشتراک کر لیتے ہیں.کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل میں شریک نہیں ہوتے صرف زبان سے تائید کر دیتے ہیں مگر دل سے اُس بدی کے مخالف ہوتے ہیں.کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نہ عمل سے شامل ہوتے ہیں، نہ زبان سے شامل ہوتے ہیں، نہ دل سے شامل ہوتے ہیں لیکن وہ مقابلہ بھی نہیں کرتے خاموش ہوتے ہیں.کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدی کے خلاف اظہار ناراضگی بھی کر دیتے ہیں لیکن پوری کوشش اس کو روکنے کیلئے نہیں کرتے.قومی سزا میں یہ سارے کے سارے شریک ہو جاتے ہیں لیکن جو سزا شخصی ہوتی ہے اس میں ہر ایک کے سلوک میں فرق کیا جاتا ہے.اِس جگہ عَفَوْنَا عَنْكُمْ سے مراد قومی سزا ہی ہے.یعنی اِس جرم کی بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم جو سزا ملنی تھی.حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ روک دی گئی.افراد کے شخصی جرم جس کا اِس میں ذکر نہیں.جیسا کہ ایک آیت چھوڑ کر بعد کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شخصی طور پر جو لوگ بڑے مجرم تھے ان کو سزا دی گئی تھی.لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ کی تشریح لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ یعنی یہ فضل ہم نے اس لئے کیا ہے تاکہ تم ہماری رحمت کے قدردان بن جاؤ اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ اﷲ تعالیٰ کیسا رحیم ہے اور اس کی رحمت کی وسعت کو دیکھ کر تم بار بار اِس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو.وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ۰۰۵۴ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے موسیٰ کو کتاب (یعنی تورات) اور فرقان دیئے تاکہ تم ہدایت پاؤ.حَلّ لُغَات.اَلْفُرْقَانَ.فُرْقَانٌ در اصل فَرَقَ کا مصدر ہے.چنانچہ کہتے ہیں فَرَقَ بَیْنَہُمَا
Page 59
فُرْقَانًا اَيْ فَصَلَ اِبْعَاضَھُمَا یعنی دو چیزوں کے حصوں کو جدا جدا کر دیا اور جب فَرَقَ لِفُـلَانٍ اَمْرٌ اَوْ رَاْیٌ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بَیَّنَ وَاتَّضَحَ فلاں کے لئے اس کی رائے اور معاملہ کی حقیقت واضح اور اچھی طرح ظاہر ہو گئی.نیز کہتے ہیں.فَرَقَ لَہٗ عَنِ الشَّیْ ءِ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ بَیَّنَہٗ اس کے سامنے کسی بات کو اچھی طرح بیان کر دیا.علاوہ ازیں اَلْفُرْقَانُ کے معنے ہیں اَلقُرْاٰنُ قرآن مجید.کُلُّ مَا فُرِقَ بِہٖ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ ہر وہ بات جس سے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہو جائے.اَلنَّصْرُ.مدد.اَلْبُرْھَانُ.دلیل.اَلصُّبْحُ اَوِ السَّحَرُ صبح یا سحری کا وقت.اِنْفِرَاقُ الْبَحْرِ سمندر کا دو ٹکڑے ہونا.اَلتَّوْرَا ۃُ تورات کو بھی فرقان کہتے ہیں.نیز بدر کی جنگ کو بھی یَوْمُ الْفُرْقَانِ کے نام سے موسوم کرتے ہیں (اقرب) فُرْقَان کے اصل معنے توکُلُّ مَا فُرِقَ بِہٖ بَیْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ کے ہیں.لیکن لغت والوں نے اس لفظ کے ذیل میں قرآن مجید.تورات اور سمندر کے دو ٹکڑے ہونے کے بھی معنے کئے ہیں.یہ استنباطی معنے ہیں نہ کہ لغوی.کیونکہ مذکورہ اشیاء کے ذریعہ سے مختلف مذاہب والوں کے نزدیک حق و باطل میں تمیز ہو گئی.اس لئےان کو فرقان کہا گیا.تَھْتَدُوْنَ.اِھْتَدٰی سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے.اور اِھْتَدٰی ھَدٰی سے باب اِفتعال ہے.ھَدَاہُ اِلَی الطَّرِیْقِ بَیَّنَہٗ لَہٗ اسے رستہ بتایا.ھَدَی العُرُوْسَ اِلٰی بَعْلِہَا زَفَّھَا اِلَیْہِ دُلہن کو اس کے خاوند تک لے گیا.ھَدَی فُلَانًا: تَقَدَّمَہٗ اس کے آگے آگے چلا.کہتے ہیں جَاءَ تِ الْـخَیْلُ یَھْدِیْہَا فَرَسٌ اَشْقَرُ اَیْ یَتَقَدَّ مُہَا.گھوڑے آئے جبکہ ان کے آگے آگے ایک سرخ رنگ کا گھوڑا دوڑتا چلا آ رہا تھا.(اقرب) پس ھَدٰی کے تین معنی ہیں راستہ دکھانا.راستہ تک پہنچانا اور آگے آگے چل کر منزلِ مقصود تک لئے جانا.قرآن کریم میں بھی ھَدَایَۃ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے.ایک معنی اس کے کام کی طاقتیں پیدا کر کے کام پر لگا دینے کے ہیں.مثلاً قرآن کریم میں آتا ہے اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى (طٰہٰ :۵۱) یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال کچھ طاقتیں پیدا کیں پھر اسے اس کے مفوضہ کام پر لگا دیا.دوسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے ہدایت کی طرف بلانے کے معلوم ہوتے ہیں.مثلاً فرمایا.وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا (السَّجدة :۲۵) اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو تورات کی طرف بلاتے تھے.تیسرے معنی ہدایت کے قرآن کریم سے چلاتے لئے آنے کے ہیں جیسے کہ جنتیوں کی نسبت آتا ہے کہ وہ کہیں گے.اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا (الاعراف:۴۴) سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو ہمیں جنت کی طرف چلاتا لایا اور جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا.اسی طرح ہدایت کے معنی سیدھے راستہ کے ساتھ موانست پیدا
Page 60
کرنے کے بھی ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے.وَ مَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ(التّغابن :۱۲) جو اللہ پر کامل ایمان لاتا ہے.اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت سے موانست پیدا کر دیتا ہے اور اچھی باتوں سے اسے رغبت ہو جاتی ہے.اس آیت میں راہ دکھانے کے معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو ایمان لاتا ہے اسے راہ تو پہلے ہی مل چکا.ہدایت کے معنی کامیابی کے بھی قرآن کریم میں آتے ہیں سورۂ نور میں منافقوں کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ انہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو وہ ضرور اس کے لئے نکل کھڑے ہوں گے لیکن عمل ان کا کمزور ہے.فرماتا ہے قسمیں نہ کھائو عملاً اطاعت کرو.کیونکہ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے.پھر فرماتا ہے اے رسول ! ان سے کہہ دے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو.پھر اگر اس حکم کے باوجود تم پھر گئے تو رسول پر اس کی ذمہ واری ہے.تم پر تمہاری.اور یاد رکھو کہ اِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا (النّور: ۵۵) اگر تم رسول کی بات اس بارہ میں مان لو گے تو نقصان نہ ہو گا بلکہ تم کا میاب ہو جائوگے اور فتح پائو گے.چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے اَلَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ( محمد :۱۸) جو لوگ اس ہدایت کو جو انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے.اپنے نفس میں جذب کر لیتے ہیں.اللہ تعالیٰ انہیں اور ہدایت عطا کرتا ہے.قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ ہدایت کسی ایک چیز کا نام نہیں بلکہ اس کے بے انتہا مدارج ہیں.ہدایت کے ایک درجہ سے اوپر دوسرا درجہ ہے.اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے جاذب ہو جاتے ہیں انہیں ایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ سے روشناس کرایا جاتا ہے.ھُدًی.اَلرَّشَادُ.سیدھے راستہ پر ہونا.اَلْبَیَانُ بیان کرنا.اَلدَّ لَالَۃُ.کسی امر کی طرف رہبری کرنا (اقرب) اَلْھَدَایَةُ.اَلدَّلَالَۃُ بِلُطْفٍ یعنی ہدایت (جو ھُدًی کاہم معنی دوسرا مصدر ہے) کے معنی محبت اور نرمی سے کسی امر کی طرف رہبری کرنے کے ہیں.(مفردات)امام راغب کے نزدیک ہدایت کا لفظ قرآن کریم میں مندرجہ ذیل چار معنوں میں آتا ہے (۱) ہر عقل یا سمجھ یا ضروری جزوی ادراک کی طاقت رکھنے والی شے (جیسے حیوانات وغیرہ کہ اِدراکِ کامل ان کو حاصل نہیں ہوتا صرف جزوی یا سطحی اِدراک ایسے ضروری امو رکا جو ان کی حیات اور محدود عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے) کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام کا طریق بتانا.اس کی مثال قرآن کریم میں یہ ہے.رَبُّنَا اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى (طٰہٰ:۵۱) یعنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی عقل یا سمجھ یا اس کے ضروری تقاضوں کے مطابق اسے رہنمائی کی (میرے نزدیک اس جگہ ھَدٰی کے معنے یہ ہیں کہ ہر شے میں مناسب قوتیں پیدا کر کے پھر انہیں کام پر لگا دیا کیونکہ صرف قوتوں کا موجود ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ انہیں ابتدائی حرکت دے کر کام پر لگانا ان کی حیات کے شروع کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے.بچہ پیدا ہوتا ہے تو گو پیدائش سے پہلے آلاتِ تنفّس کامل طور پر موجود ہوتے ہیں مگر باہر نکلنے
Page 61
کے بعد جب تنفّس کے آلات کو ہوا لگنے یا پانی کا چھینٹا دینے سے ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے بچہ کی عملی زندگی درحقیقت اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جس طرح ایک گھڑی کے اندر سب ہی پُرزے موجود ہوتے ہیں مگر جب تک اُسے ُکنجی دے کر حرکت نہ دی جائے پُرزے کام کرنا شروع نہیں کرتے غرض حیات کو شروع کرنے سے پہلے ایک ابتدائی دھکے کی ہر شے کو ضرورت ہوتی ہے اور ہدایت سے مراد وہی حرکت اُولیٰ ہے اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو مناسب قویٰ کے ساتھ پیدا کیا ہے او رپھر حرکت ِ اُولیٰ دے کر اسے مفوضہ کام پر لگا دیا ہے) علّامہ راغب کے نزدیک ہدایت کے دوسرے معنے اس ارشاد کے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے بندوں تک پہنچاتا ہے اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے.وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا (سجدۃ:۲۵) ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے امام مقرر کئے جو ہمارے الہام سے لوگوں کو ہماری طرف بلاتے تھے.ہدایت کے تیسرے معنے ان کے نزدیک اس توفیق کے ہیں جو ہدایت پانے والوں کو ملتی ہے یعنی ہدایت ملنے کے بعد جو عمل کی توفیق یا فکر کی بلندی پیدا ہوتی ہے یا مزید ہدایت کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ بھی ہدایت کہلاتی ہے اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے اَلَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى(محمد:۱۸) جو لوگ ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے (یعنی عمل کی توفیق اور ہدایت کے سلسلہ میں مزید فکر کرکے اور علوم حاصل کرنے کا موقع عطا کرتا ہے).چوتھے معنی ہدایت کے انجام بخیر کے اور جنت کو پالینے کے ہیں.اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے.سَيَهْدِيْهِمْ وَ يُصْلِحُ بَالَهُمْ(محمد:۶) اللہ تعالیٰ ان کا ا نجام بخیر کر کے انہیں جنت تک پہنچا دے گا اور ان کے حالات کو درست کر دے گا اور قرآن کریم میں جہاں یہ آتا ہے.يَهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا (الانبیاء:۷۴)وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت دیتے تھے یا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ(الرعد:۸) ہر قوم میں ہادی آیا ہے اس جگہ ہدایت سے مراد لوگو ںکو ہدایت کی دعوت دینے کے ہیں اور ایسی آیات جیسے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ (القصص:۵۷) اور ایسی آیات جن میں یہ ذکر ہے کہ کافروں اور ظالموں کو ہدایت نہیں مل سکتی.اس سے مراد تیسری اور چوتھی قسم کی ہدایتیں ہیں یعنی ہدایت پاجانے کے بعد توفیق ِ عمل کا ملنا یا نورِ ایمان کا عطا ہونا یا جنت میں داخلہ کی نعمت کا حصول.پس ان آیات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کفار کو مذکور ہ بالا انعامات نہیں مل سکتے (اور یہ ظاہر ہے کہ جو دوسری قسم کی ہدایت یعنی دعوت انبیاء کو قبول نہیں کرتا.وہ تیسری اور چوتھی قسم کی ہدایتوں کو جو دوسری قسم کی ہدایتوں کے نتائج ہیں حاصل نہیں کر سکتا) (مذکورہ بالا تمام مضمون سوائے ان عبارتوں کے جو خطوط و حدانی میں ہیں عربی کی مشہور لغت کی کتاب مفردات راغب سے لیاگیا ہے)
Page 62
اِھْتَدٰی کے ایک معنے سب سے آگے ہو جانے کے بھی ہیں.چنانچہ کہتے ہیں اِھْتَدَی الْفَرَسُ الْخَیْلَ صَارَ فِیْ اَوَائِلَھَاکہ فلاں گھوڑا باقی قافلہ کے گھوڑوں کے آگے آگے چلا ( اقرب) پس تَھْتَدُوْنَ کے معنے ہدایت پانے کے علاوہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تا تم سب لوگوں سے آگے نکل جاؤ.ان کے پیش رَو ہو جاؤ.تفسیر.آیت وَاِذْ اٰتَیْنَا … الخ میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور بنی اسرائیل کے فعل کے تقابل کی طرف اشارہ اس آیت میں ضمنی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان چالیس راتوں میں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے.کیا کچھ دیا گیا تھا اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم تو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اتنا کام کر رہے تھے اور ان کی ترقی کے سامان پیدا کر رہے تھے.اور یہ لوگ ایک زندہ خدا اور محسن خدا کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کی پرستش میں مشغول تھے.یہ تقابل اﷲ تعالیٰ کے فعل کا اور بنی اسرائیل کے فعل کا بنی اسرائیل کے جرم کو ایسا واضح کر دیتا ہے کہ کوئی عقلمند اس سے متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا.لَعَلَّکُمْ تَھْتَدُوْنَ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہم تمہاری ہدایت کے سامان کر رہے تھے اور تم اپنی گمراہی کے سامان کر رہے تھے.کتاب اور فرقان جو اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دئے گئے.ان کی غرض تو یہ تھی کہ وہ اجمالی ایمان جو بنی اسرائیل کو حاصل تھا اسے تفصیلی ایمان سے بدل دیا جائے.مگر بنی اسرائیل نے ان ایام میں اس اجمالی ایمان کو بھی کھو دیا.اور شرک میں مبتلا ہو گئے.حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام اِس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلی دفعہ آیا ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس جگہ بعض امور بیان کر دینے ضروری ہیں.حضرت موسیٰ ؑکے بنی اسرائیل میں سے ہونے کا ثبوت قرآن کریم سے قرآنِ کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے.اور بنی اسرائیل کے سلسلہ نبوت کی پہلی کڑی تھے.جس کی آخری کڑی کے طور پر حضرت عیسٰی علیہ السلام ظاہر ہوئے.سورہ اعراف میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کے ساتھیوں نے کہا.اَتَذَرُ مُوْسٰى وَ قَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ (الاعراف :۱۲۸) اے فرعون! کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ ملک میں فساد کریں.اِسی طرح ایک درجن سے بھی زیادہ مواقع پر قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم قرار دیا گیا ہے.گو اس کی یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ قوم سے ان کے ماننے والے لوگ مراد لئے جائیں لیکن قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے.پس آپ کو ماننے والے بھی سوائے شاذونادر کے بنی اسرائیل ہی ہوںگے
Page 63
پس قوم سے مراد اس صورت میں بھی بنی اسرائیل ہی بنتے ہیں.مگر ایک آیت قرآن کریم میں ایسی ہے جو قوم کے لفظ کو بالکل واضح کر دیتی ہے.اﷲ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے.فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ(یونس :۸۴) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے.اس جگہ قوم سے مراد بہر حال بنی اسرائیل ہی ہو سکتے ہیں.کیونکہ جب یہ فرمایا کہ ان کی قوم کے تھوڑے آدمی اُن پر ایمان لائے تھے.تو قوم سے مراد مومن نہیں ہو سکتے بلکہ قوم سے مراد نسلی قوم ہی لی جا سکتی ہے.نئے محققین کی اس بات کو ثابت کرنے کی چھ دلیلیں کہ حضرت موسیٰ ؑ بنی اسرائیل میں سے نہ تھے آج کل کے نئے محقق اِس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے بلکہ وہ کسی مصری قوم میں سے تھے اور وہ اِس کے مندرجہ ذیل دلائل دیتے ہیں:.اوّل موسیٰ کا نام مصری زبان میں ہے.چنانچہ مصری زبان میں ’’ مَوسِے‘‘ بچے کو کہتے ہیں.بریسٹڈ اپنی کتاب ’’ ڈان آف کانَشنس‘‘ میں لکھتا ہے کہ مصریوں میں ‘‘ آمن موسٰے‘‘ اور ’’ پٹا موسٰے‘‘ قسم کے نام پائے جاتے ہیں جن کے معنے ہیں.امون ( ایک مصری دیوتا) کا بچہ.پٹا( ایک مصری دیوتا) کا بچہ.پروفیسرسِگْمَنڈ فَرَائِیڈ اپنی کتاب ’’ مَوْزِزْ اَینڈ مَانوتھی اِزم‘‘.Moses and Monotheism میں لکھتے ہیں کہ ان ناموں کے علاوہ مصری بادشاہوں کے نام بھی اس رنگ کے پائے جاتے ہیں.جیسے ’’ آہ موسے‘‘.’’ تُھٹ موسے‘‘.’’راموسے‘‘.صفحہ۱۴.یہ ’’ راموسے‘‘ وہی ہے جس کے نام کو بائبل میں ’’ رعمسیسں لِکھا گیا ہے.را سورج کا دیوتا تھا.پس ’’راموسے‘‘ کے معنے ہوئے.سورج دیوتا کا دیا ہوا بیٹا.یہ لوگ کہتے ہیں کہ ’’ موسٰے‘‘ کے ساتھ جو نام تھا وہ گر گیا اور ’’ موسیٰ‘‘ خالی موسیٰ ؑ کے نام سے مشہور ہو گیا.دوسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ توحید کنعانی قبائل میں نہیں پائی جاتی.توحید کا عقیدہ مصر کے ایک بادشاہ نے ایجاد کیا تھا.اس بادشاہ کا نام’’ عمون ہو تپ چہارم ‘‘ بتایا جاتا ہے.اس بادشاہ نے ایک خدا کی جس کا نام وہ ’’اتون‘‘بتاتا تھا پرستش کی اور لوگوں سے کروائی.اتون کا لفظ پرانی کتب میں سورج دیوتا کے لئے استعمال ہوتا تھا.بیان کیا جاتا ہے کہ ہلیو پولس کے مقام پر سورج دیوتا کا ایک بڑا مندر تھا جس میں سورج کی پوجا کی جاتی تھی.اس مندر کے ساتھ تعلق رکھنے والے بہت سے پُجاری فلسفیانہ خیالات کے ہوئے ہیں.انہوں نے آہستہ آہستہ سورج دیوتا کو ایک مادی دیوتا سے اخلاقی دیوتا کی شکل میں بدلنا شروع کر دیا.اسی تصوّر کو ’’ عمون ہو تپ ‘‘ نے واحدخدا کے تصوّر کا جامہ پہنایا اور مصر میں اس کو رائج کیا.اُس کا ایک فقرہ نقل کیا جاتا ہے جسے بریسٹڈنے اپنی تاریخ مصر
Page 64
(HISTORY OF EGYPT)میں درج کیا ہے اور وہ یہ ہے’’ اے یکّہ و تنہا خدا تیرے سوا اور کوئی نہیں.‘‘ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ توحید کے خیال کا بانی وہی تھا اور اس نے ملک میں جبراً اس خیال کی اشاعت کی.اس بادشاہ نے بُت خانے بھی تُڑوائے.چونکہ ’’ عمون ہو تپ‘‘ مشرکانہ نام تھا اس لئے اس بادشاہ نے اپنا نام بھی ’’اختاتون‘‘ رکھا گویا اپنے آپ کو ’’ اتون‘‘ یعنی واحد خدا کی طرف منسوب کیا.تیسری دلیل ان لوگوں کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل میں ختنہ رائج کیا اور ختنہ کا دستور مصری ہے.پس معلوم ہوا کہ موسیٰ ؑ مصری تھے.چوتھی دلیل یہ دی گئی ہے کہ اِس اختاتون بادشاہ یا عمون ہو تپ بادشاہ کی تعلیم میں کہیں بعث بعد الموت کا ذکر نہیں کیا گیا ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی تعلیم میں کہیں بعث بعد الموت کا ذکر نہیں.پانچویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ مصری سؤرسے نفرت کرتے تھے ایسا ہی موسوی تعلیم میں سؤر سے نفرت دلائی گئی ہے.چھٹی دلیل یہ دی گئی ہے کہ موسیٰ کی نسبت آتا ہے کہ وہ اچھی طرح اپنے خیالات ظاہر نہ کر سکتے تھے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصری تھے.اور عبرانی زبان اچھی طرح نہ بول سکتے تھے.پس معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام مصری تھے اور ان لوگوں کے خیال میں وہ عمون ہو تپ المعروف بہ اختاتون بادشاہ کے متبعین میں سے تھے.اختاتون کے بعد پھر دوبارہ مصری مذہب قائم ہو گیا اور شرک نے جگہ لے لی تب اُن میں اختاتون کی موحّدانہ تعلیم کے پھیلنے کا کوئی امکان نہ رہا تو حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام نے ایک غیر قوم یعنی بنی اسرائیل کی طرف توجہ کی جو مصریوں کے ظلم کا تختۂ مشق بنی ہوئی تھی اور عام مصری خیالات کو اپنی منافرت کی وجہ سے چھوڑنے پر آمادہ کی جا سکتی تھی.اسرائیلیوں نے اس وجہ سے کہ وہ موسیٰؑ مصری کے خیالات کو مان کر مصری قوم کے خیالات کی تردید کرنے والے ہو جاتے تھے جو اُن کی دشمن تھی جلدی سے اس دین کو قبول کر لیا اور جب اس دین کو قبول کرنے کی وجہ سے مصر میں ان کے لئے کوئی جگہ نہ رہی تو حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے ساتھ انہوں نے اس ملک سے ہجرت کی اور کنعان کی طرف آ گئے.اب میں ان چھ دلیلوںکا جو پیش کی جاتی ہیں مختصراً جواب دیتا ہوں.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی مصری قوم میں سے ثابت کرنے کے دلائل کا ردّ پہلی دلیل یہ دی گئی ہے کہ موسیٰ ؑ کا نام مصری ہے اس لئے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام مصری ہیں.یہ دلیل نہایت ہی مضحکہ خیز ہے.بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے اور ادنیٰ حیثیت میں رہتے تھے اس لئے لازمی طور پر انہیں مصری تہذیب اور مصری
Page 65
اقوام کے اثر سے متأثر ہونا چاہیے تھا.ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے انگریز ہیں.ہزار میں سے ایک بھی انگریزآبادی کے لحاظ سے نہیں لیکن باوجود اس کے ہندوستان میں ہزاروں آدمی جیمز(JAMES) جونز(JONES) اور ٹامس( THAMAS) وغیرہ ناموں سے اپنے خیال میں اپنی عزت افزائی کر رہے ہیں اُن کے رنگ کوئلوں کی طرح کالے ہیں نسلاً وہ چوہڑوں چماروں میں سے ہیں.زبان انگریزی جاننا تو الگ رہا.بعض اُن میں سے ایسے ہیں کہ لفظ عیسائی یا انگریز بھی نہیںبول سکتے.عیسائی کو’’ ہسائی‘‘ کہتے اور انگریزکو ’’ گریج‘‘ کہتے ہیں مگر پھر بھی ٹامس، جونز اور اس قسم کے اور نام انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کیا ان ناموں کو دیکھ کر کوئی مؤرّخ یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب سمجھا جائے گا کہ وہ انگریزی نسل کے آدمی ہیں.آخر انسانی استدلال کی کوئی نہ کوئی قیمت چاہیے.ایک مؤرّخ کو رائے قائم کرنے سے پہلے ہر قسم کے حالات کو سوچ کر رائے قائم کرنی چاہیے.مَیں حیران ہوں یہ یوروپین مؤرّخ آخر کس بناء پر ایسی جلدی نتائج نکالنے کی طرف مائل ہو گئے ہیں.وہ موسیٰ ؑ اور اُن کے چند ساتھیوںکے ناموں پر حیران ہیں.وہ ہندوستان میں آئیں ہم ان کو ہزاروں کالے کلوٹے نسلاً چوہڑے اور چمار زبان انگریزی سے نابلد ٹامس( THAMAS)جیمز اور جونز دکھا دیتے ہیں.اسی طرح عورتوں کا حال ہے سینکڑوں عورتیں ایسی ہیں جو عیسائی تو نہیں لیکن کسی کان ونٹ(CONVENT)میں پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام یا اپنے بچوںکے نام انگریزی طرز پر رکھ لئے ہیں اور بعض جگہ پر ایک ایک انگریزی نام ہے اور ایک ایک اسلامی یا ہندو انہ نام اور وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں میں اسی انگریزی نام سے مشہور ہوتی ہیں کوئی ثریاّ ہے اور وہ اپنی ہمجولیوں میں ڈالی (DOLLY)کہلاتی ہے کوئی رام کول ہے اور وہ اپنی سہیلیوں میں جین (JANE) کہلاتی ہے کیا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ وہ انگریز ہیں پھر ان سینکڑوں اور ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر کیوں نہ یہ نتیجہ نکالا جائے کہ اگر موسیٰ ایک مصری نام ہی ہے تو موسیٰ علیہ ا لسلام کے والدین نے یا جس نے بھی یہ نام رکھا اس نے مصری اثر کے نیچے اس بچے کو ایک مصری نام دے دیا اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل اور قرآن کریم کے رو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش پر فرعون کی سختی سے بچانے کے لئے ان کی والدہ نے خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریا میں پھینک دیا تھا اور اُن کو مصری شاہی خاندان کی ایک عورت نے وہاں سے اُٹھایا اور پالا تو اس میں کونسے تعجب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام مصری تھا.آخر جو بچّہ دریا کے کنارے پڑ اہوا پایا گیا تھا.اس کا نام کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا اگر اسے اُٹھانے والوں نے اس کا نام اپنی زبان میں رکھا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے.
Page 66
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مصری زبان میں ہونا ان کے مصری قوم میں سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا پس فرض کرو یہ مصری نام ہے تو بھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام مصری تھے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے بچپن کے واقعات میں ایک ایسی کڑی موجود ہے جو ان کے نام کے مصری ہونے کے امکان کو ثابت کرتی ہے تو پھر اس نام سے ان کی مصری قومیّت کا نتیجہ نکالنا کس طرح درست ہو سکتا ہے.غرض مصری نام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے مصری ہونے کا استدلال نہایت ہی کمزور ہے اور اس استدلال سے زیادہ بودا اور کمزور استدلال کم ہی ہو سکتا ہے.بائبل کا بیان اس واقعہ کے متعلق مندرجہ ذیل ہے.بنو لاوی میں سے ایک مرد نے اپنے قبیلہ کی عورت سے شادی کی’’ وہ عورت حاملہ ہوئی اور بیٹا جنی اور اس نے اسے خوبصورت دیکھ کر تین مہینے تک چھپا رکھا اور جب آگے کو چھپا نہ سکی تو اُس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا بنایا اور اُس پر لا سااور رال لگایا اور لڑکے کو اُس میں رکھا اور اُس نے اسے دریا کے کنارے پر جھاؤ میں رکھ دیا اور اس کی بہن دُور سے کھڑی دیکھتی تھی کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ.تب فرعون کی بیٹی غسل کرنے کو دریا پر اُتری اور اُس کی سہیلیاں دریا کے کنارے پر پھرنے لگیں اس نے جھاؤ میں ٹوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اُسے اُٹھالے.جب اُس نے اُسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ روتا ہے اُسے اُس پر رحم آیا اور بولی یہ کسی عبرانی کا لڑکا ہے تب اس (یعنی موسیٰ ) کی بہن نے فرعون کی بیٹی کو کہاکہئے تو میں جاکے عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تجھ پاس لے آؤں تاکہ وہ تیرے لئے اس لڑکے کو دودھ پلائے.فرعون کی بیٹی نے اسے کہا کہ جا، وہ چھوکری گئی اور لڑکے کی ماں کو بلایا.فرعون کی بیٹی نے اسے کہا کہ اس لڑکے کو لے اور میرے لئے دودھ پلا.مَیں تجھے دوماہہ دُوںگی.اُس عورت نے لڑکے کو لیا اور دودھ پلایا.جب لڑکا بڑھا وہ اسے فرعون کی بیٹی پاس لائی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا.اس نے اس کا نام موسیٰ رکھا اور کہا اس سبب سے کہ میں نے اسے پانی سے نکالا.‘‘ (خروج باب۲ آیت ۲ تا ۱۰) قرآن کریم میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے.وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ١ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَ لَا تَخَافِيْ وَ لَا تَحْزَنِيْ١ۚ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَ جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.فَالْتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّ حَزَنًا١ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ.وَ قَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَ لَكَ١ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ١ۖۗ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.(القصص:۸تا۱۰) یعنی موسیٰ ؑکی پیدائش پر ہم نے موسیٰ ؑ کی والدہ کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلا.پھر جب تجھے ڈر ہو کہ بچے کی پیدائش کا راز فاش ہو جائے گا تو تُو اس کو دریا میں ڈال دیجیئو اور ڈریو نہیں اور نہ ہی غم کیجیئو(سورۂ طٰہٰ ع۲ میں دریا میں ڈالنے کے متعلق یہ بیان کیا
Page 67
گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی والدہ کو یہ کہا گیا تھا کہ اُنہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈالا جائے) ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے اور اس کو اپنا رسول بنائیں گے.پھر اُس کو آلِ فرعون نے دریا کے پاس سے اُٹھا لیا تاکہ وہ اُن کا دشمن ہو اور غم کا موجب ہو.فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر یقیناً خطا کار تھے اور فرعون کے خاندان کی ایک عورت نے فرعون سے کہا یہ میرے لئے اور تیرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گا اِس کو مارو نہیں ممکن ہے یہ ہمیں نفع دے ( اچھا غلام ثابت ہو) یا ( اگر بہت ذہین نکلے ) تو ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ حقیقت کو جانتے نہیں تھے.ان حوالوں سے ثابت ہے کہ قرآنِ کریم اور بائبل کے رو سے فرعون کے گھر کی ایک عورت نے جو بائبل کے بیان کے مطابق فرعون کی بیٹی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اُٹھایا اور پالا.اور بائبل صاف کہتی ہے کہ اس فرعون کی بیٹی نے ہی موسیٰ علیہ ا لسلام کا نام رکھا تھا اور اگر ایسا ہوا ہو تو فرعون کی بیٹی نے آخر اپنا مصری نام ہی رکھا ہو گا.پس مصری نام کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو مصری قرار دینا بالکل خلافِ عقل ہے.پنجاب میں اس قسم کی کم از کم دومثالیں پائی جاتی ہیں.دو مشہور انگریزوں نے دو ہندوستانی لڑکے پا لے اور ان کے انگریزی نام رکھے اور وہ لڑکے انہی انگریزی ناموں سے اب تک مشہور ہیں.ان میں سے ایک واربرٹن خاندان کی طرف منسوب ہے اور دوسرا ہندوستانی نوجوان ڈاکٹر مارٹن کے خاندان کی طرف منسوب تھا جس خاندان کا ایک فرد ابی سینیا میں وزیر کے عہدہ پر بھی متمکن رہا ہے.وہ افراد جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں خالص ہندوستانی الاصل ہیں مگر چونکہ انگریزوں نے ان کو پالا تھا اور انگریزوں نے ہی اُن کا اپنی طرز پر نام رکھا اس لئے وہ انگریزی ناموں سے ہی مشہور ہیں.علاوہ ازیں میرے نزدیک اس امر کا بھی کوئی کافی ثبوت پیش نہیں کیا گیا کہ موسیٰ واقعہ میں مصری نام ہے اور نہ اس امر کا کوئی کافی ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ موسیٰ عبرانی نام نہیں ہے.جو لوگ موسیٰ کو مصری نام قرار دیتے ہیں وہ بعض مصری ناموں سے استدلال کر تے ہیں کہ اُن کا ایک حصّہ موسیٰ کے نام پر مشتمل ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محققینِ زبان کا اِس میں اختلاف ہے بلکہ ایک بھی محقق ایسا نہیں جو اس لفظ کا تلفظ جسے موسیٰ قرار دیا گیا ہے موسیٰ بتاتا ہو بلکہ کوئی اسے ’’ مَوْسِے‘‘ پڑھتا ہے اور کوئی اسے ’’ مَیس‘‘ اور کوئی ‘‘میسو‘‘ بتاتا ہے جس کے معنے بچے کے ہیں اور یہ نام کبھی اکیلا ہوتا ہے اور کبھی کسی اور نام کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ مصری شاہی خاندان کے مندرجہ ذیل ناموں کا یہ حصّہ ہے.تھاٹ میس(THOTMS).آہ میس(AHEMS).رامیسو(RAMESSU) اب یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ ؑ کے تلفّظ اور اِس تلفّظ میں بہت بڑا فرق ہے.اوّلؔ موسیٰ ؑ میں حروفِ علّت میں سے واؤ
Page 68
نوح علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ انسان کو ترقی کی بلندی پر ایک منزل اور اونچا لے گئے مگر انسان نے گو نوح علیہ السلام کے ذریعہ سے روحانی اور اخلاقی اور ذہنی طو رپر ترقی کی مگر ابھی وہ مقصد حاصل نہ ہوا تھا جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا تھا چنانچہ آپ کے بعد اور نبی آیا اور اس کے بعد اور.اور اس کے بعد اور.اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ظاہر ہوئی اور آپؐ نے تمام راز ہائے سربستہ جو انسان پر اب تک پوشیدہ تھے ظاہر کر دیئے اور دینی اور ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لئے جس قدر ضروری امور تھے وہ سب کے سب بیان کر دیئے اور گویا علمی طور پر مذہب کو کمال تک پہنچا دیا.اور اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ (المائدۃ:۴) کا اعلان کر دیا مگر جب تک اس اعلیٰ تعلیم کو جامہء عمل نہ پہنایا جاتا اس کے نزول کی غرض پوری نہ ہو سکتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری طرح کامیاب نہیں کہلا سکتی تھی پس اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے سورۂ فاتحہ میں مسلمان کو اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ کی دعا سکھائی اور کہا کہ ہمیشہ اپنے سامنے یہ مقصد رکھو کہ جس مقامِ محمود کو سامنے رکھ کر اس دنیا نے شروع سے روحانی سفر اختیار کیا ہے اور جس کی مختلف منزلوں تک مختلف انبیاء انسانوں کو پہنچاتے چلے آئے ہیںاور جس کی آخری منزل تک پہنچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا ہے اس تک تم پہنچ جائو.پس سارے کے سارے منعم علیہ گروہ کی نعمتو ں سے ہمیں حصہ دے کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا! ہم کو آدم کی امت کی نیکیاں دے او رپھر ہماری ذہنی ترقی نوح کی امت کی طرح کر پھر ابراہیم کی امت کے مقام پر پہنچا اور پھر موسیٰ کی امت کے کمالات ہمیں دے اور پھر مسیح کی روحانیت کے اثر سے ہمیں حصہ دے اور اس طرح منزل بہ منزل روحانی بلندیوں پر چڑھاتے ہوئے بالآخر مقام محمدؐ پر ہم کو قائم کر دے تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو اور وہ مقام محمود پر ـفائز ہو جائیں.غرض صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ سے مُراد انسانی کمال کی وہ آخری منزل ہے جس کی طرف شروع سے انسانی قافلہ بڑھتا آرہا ہے اور جس کی مختلف منزلوں کی راہنمائی مختلف زمانہ کے انبیاء کے سپرد تھی اور جس کی آخری منزل تک پہنچانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا تھا اور اس دعا کے ذریعہ اس امت محمدؐیہ کے افراد درخواست کرتے ہیں کہ الٰہی دین کی تکمیل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تو نے کر ہی دی ہے اب یہ امر باقی ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال بھی اس دین کے مطابق ہو جائیں اور ہم ان تمام مخفی اور اعلی قوتوں کا اظہار کریں جن کی مختلف انبیاء کے ذریعے سے نشوونما کی جا چکی ہے اور جن کا پیدا کرنا انسانی پیدائش کا آخری اور اعلیٰ مقصد ہے سو اس کام کے لئے ہم کھڑے ہو گئے ہیں اب تُو ہماری مدد کر اور ان سب منازل
Page 69
دوسرے یہ خیال کرنا بعید از قیاس ہے کہ سالہا سال ایک بچہ کاکوئی نام ہی نہ رکھا گیا ہو.اگر ہم عربی زبان پر غور کریں تو اس سے بھی موسیٰ ؑکے نام کی تصدیق ہوتی ہے.کیونکہ عربی زبان کے رو سے موسیٰ ؑکے لفظ کے معنے کٹے ہوئے کے ہوں گے اور اس نام کے یہ معنے ہو سکتے ہیں کہ گویا وہ اپنے خاندان سے کٹ کر فرعونیوں میں پالا گیا.اگر عبرانی تلفّظ کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے جو ’’موشے‘‘ ہے دیکھا جائے تو ’’ موشٰی‘‘ کے معنے عربی زبان میں نکالے ہوئے کے ہیں چنانچہ عربی میں کہتے ہیں اَوْشَی الشَّیْ ءَ.اِسْتَخْرَجَہٗ.اَوْشٰی کا اسم فاعل بنے گا.مُوْشِی (نکالنے والا) اور اسم مفعول بنے گا مُوْشٰی ( یعنی نکالا ہوا ) پس مُوشٰی کے معنے بنیں گے نکالا ہوا.اور یہ معنی بائبل کے اس فقرہ سے بالکل ملتے ہیں جو کہا گیا کہ ’’ اِس سبب سے کہ مَیں نے اسے پانی سے نکالا‘‘ پس میرے نزدیک درحقیقت موسیٰ مُوشٰی تھا جس کا عبرانی تلفّظ’’ موشے‘‘ ہے اور اس کے لفظی معنے صرف نکالے ہوئے کے ہیں.سب سے آخر میں مَیں یہ کہنا چاہتا ہوںکہ ایک طرف تویہ جدید محقّق اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ بنی اسرائیل مصر میں گئے اور نہ مصر سے واپس آئے اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل مصر میں گئے اور ان کے سردار حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام خود مصری تھے اور ان کا مذہب بھی مصری ہے.اس تضاد سے ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ ان محققین کی باتوں کی بنیاد کتنی کمزور ہے.حق یہ ہے کہ ان لوگوں نے بعض اچھی تحقیقاتیں کی ہیں لیکن اس شوق نے ان کو خراب کیا ہے کہ ہر تحقیق کے نتیجہ کو اُس مسئلہ تک محدود رکھنے کی بجائے اس کو سب مسائل پر حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح وہ ٹھوکرکھا گئے ہیں.اُن کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص آبخورا بنائے اور ساری دنیا کی پیدائش کا دعویٰ کرنے لگ جائے.آبخورا بنانا خود ایک اچھا کام ہے مگر آبخور ے کے بنانے سے کوئی شخص دنیا کا خالق نہیں بن سکتا.اگر یہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے تو یقیناً اُن کے کام کی دنیا میں بہت زیادہ قدر کی جاتی.اس دلیل کا ردّ کہ توحید کا خیال مصری ہے اور حضرت موسیٰ کا توحید کے خیالات پھیلانا ان کے مصری ہونے کی دلیل ہے دوسری دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ توحید کا خیال مصری ہے چونکہ یہ خیال حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام نے اسرائیلیوں میں پھیلایا ہے اس لئے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ ا لسلام مصری تھے.اس کے مندرجہ ذیل جواب ہیں.اوّل یہ خیال کر لینا کہ کوئی عقلی خیال محض کسی ایک قوم میں نشوونما پاتا ہے عقل کے بالکل خلاف ہے.اگر ہم اس خیال کو درست تسلیم کر لیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ دنیا کی تمام علمی ترقی صرف چار یا پانچ اشخاص کے دماغوں میں
Page 70
ہوئی ہے اور باقی دنیا نے اُس کی نقل کی ہے اور یہ خیال بالبداہت باطل ہے.دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف افراد اپنے گردوپیش کے حالات پر غور کر کے کچھ نتائج نکالتے رہے ہیں اور مختلف ممالک کے سینکڑوں آدمیوں کے خیالات میں توارد ہوتا رہا ہے اصولی خیال ایک رہا ہے.ماحول کے ماتحت کچھ کچھ تبدیلیاں مختلف مُلکوں میں ہوتی رہی ہیں.توحید کا سوال تو ایک ایسا سوال ہے جس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک مُلک کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا.ہم تو دیکھتے ہیں سائنس کے جزوی مسائل کے بارہ میں بھی ایک ایک وقت میں کئی ممالک کے سائنسدانوں نے آزادانہ طور پر تحقیقات کر کے ایک قسم کے نتائج معلوم کئے ہیں اور کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے ایک دوسرے کی چوری کی ہے بلکہ دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ یہ توارد ہوا ہے.بے تار برقی کے متعلق ہی ایک وقت میں مارکونی کے علاوہ اور سائنسدان بھی توجہ کر رہے تھے اور وہ اپنے طور پر اس بارہ میں کئی حقائق کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے.پس یہ خیال کرنا بالکل درست نہیں کہ چونکہ مصریوں میں توحید کا خیال پایا جاتا تھا اس لئے یہ خیال کسی اور قوم میں نہیں ہو سکتا تھا اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام مصری توحید کو پھیلاتے تھے اس لئے وہ مصری تھے.ایک لحظہ کے لئے فرض کر لو کہ یہ اصول بھی درست ہے تو پھر بھی اِس سے یہ نتیجہ کیونکر نکلا کہ موسیٰ ؑ مصری تھے.کیا قانونِ قدرت کا یہ بھی کوئی قاعدہ ہے کہ مصری خیال کو مصری ہی پھیلا سکتا ہے کوئی اسرائیلی نہ اُس خیال کو تسلیم کر سکتا ہے اور نہ اس کو پھیلا سکتا ہے.اگر یہ درست بھی ہے کہ توحید صرف مصر میں ہی پائی جاتی تھی تو کیا اس بات کا تسلیم کرنا ناممکن ہے کہ اسرائیلی نسل کے ایک شخص موسیٰ کو یہ خیال بھایا اور اُس نے یہ خیال اپنی قوم میں پھیلا دیا.میرے یہ جو ابات اس مسئلہ پر صرف علمی تنقید کا رنگ رکھتے ہیں ورنہ حق یہ ہے کہ نہ تو حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے توحید کا خیال ایجاد کیا اور نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام نے اس خیال کو ایجاد کیا.تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء اپنے خیالات نہیں پھیلاتے بلکہ خدا تعالیٰ کی وحی کو پھیلاتے ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ توحید کا خیال ابتدائے عالم سے دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا گیا ہے.اگر خدا ایک ہے اور اگر وہ شروع سے الہام کرتا چلا آیا ہے تو یہ سیدھی سادی بات ہے کہ وہ اپنے نبی کو یہی کہے گا کہ میں ایک ہوں.یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک خدا پہلے نبیوں سے تو یہ کہتا رہے کہ میں دو ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں لیکن ’’ عمون ہو تپ‘‘ کو آ کر یہ کہے کہ میں ایک ہوں.یہ سارا دھوکا الہام اور اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے.مذہب کی تو بنیاد ہی الہام پر ہے.اگر الہام نہیں تو مذہب صرف ایک ڈھکوسلا رہ جاتا ہے.پھر موسیٰ ؑ اسرائیلی ہوں مصری ہوں یا کچھ ہوں اُن کی ذات بالکل بے حقیقت رہ جاتی ہے.حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی عظمت اور شان
Page 71
تو خدائی الہام کی وجہ سے ہے اور اگر خدائی الہام کو تسلیم کیا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ توحید تمام انبیاء کی تعلیم کا جزو اعظم رہا ہے.خدا تعالیٰ اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لئے ’’ عمون ہوتپ‘‘ کے پیدا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا.ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم مکّہ کے رہنے والوں کے سامنے متواتر یہ بات پیش کرتا ہے کہ تمہارا داد ا ابراہیمؑ موحّد تھا اور حضرت ابراہیمؑ یقیناً حضرت موسیٰ ؑ سے پہلے کے آدمی ہیں.مکّہ کے لوگ خود مشرک تھے لیکن ان کو اس بات کی تردید کی جرأت کبھی نہ ہوئی اور ایک قول بھی کسی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا کہ مکّہ کے لوگوں نے آگے سے جھوٹے طور پر بھی کہا ہو کہ ابراہیمؑ مشرک تھا.پس یہ ایک تاریخی شہادت اِس بات کی ہے کہ قریش جو اسرائیلیوں سے دُور بستے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ ا لسلام کی نسل سے قرار دیتے تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ ا لسلام کو ایک خدا کے ماننے والا قرار دیتے تھے.موسیٰ علیہ ا لسلام نے اگر توحید ’’عمون ہوتپ‘‘ سے سیکھی تھی تو مکّہ کے ان اَنْ پڑھ لوگوں نے توحید کا علم کس سے حاصل کیا.کیا یہ بھی مصر سے سیکھ کر آئے تھے.وہ تو خود مشرک تھے ان کا تو فائدہ اس میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ ا لسلام کو مشرک قرار دیتے مگر باوجود اِس کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ ا لسلام کے موحّد ہونے کا کبھی انکار نہیں کیا.پس یہ کہنا کہ ’’ عمون ہوتپ‘‘ سے توحید شروع ہوئی ہے بالکل درست نہیں.دنیا کی مختلف تاریخیں ایک خدا کا خیال قدیم زمانہ سے پیش کرتی چلی آئی ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کے الہام نے دنیا کے ہر گوشہ میں توحید کے خیال کو زندہ اور قائم رکھا ہے.شرک سے توحید پیدا نہیں ہوئی بلکہ توحید کے بعد کمزوری اور ضعف کے دنوں میں شرک کے خیالات پیدا ہوئے ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ختنہ کی رسم جاری کرنا ان کو مصری ثابت نہیں کرتا تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ ختنہ مصریوں میں رائج تھا اور حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام نے بھی اس کی تعلیم دی.پس معلوم ہوا کہ وہ مصری تھے.اِس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو یہ استدلال غلط ہے کہ ختنہ کی رسم کے جاری کرنے کی وجہ سے موسیٰ مصری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ فرض کرو ختنہ مصر ہی میں رائج تھا تو کیوں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ بنی سرائیل نے مصر کی رہائش کے دنوں میں مصریوں کے اثر کے ماتحت ختنہ کرنا شروع کر دیا.دوسرے یہ بات بھی غلط ہے کہ ختنہ مصریوں میں ہی رائج تھا.بائبل کہتی ہے کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ ا لسلام نے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام سے کئی سو سال پہلے خدا تعالیٰ کے حکم سے کروایا اور اپنی اولاد کے لئے ختنہ کرانا ضروری قرار دیا اور نہ صرف خود اپنا ختنہ کرایا بلکہ حضرت اسماعیل علیہ ا لسلام اور حضرت اسحاق ؑ کا بھی ختنہ کرایا.اس بات کا ثبوت کہ بائبل کا یہ بیان درست ہے یہ ہے کہ عرب جن کے سوشل تعلقات اسرائیلیوں
Page 72
سے اچھے نہیں تھے اور جو کبھی مصر نہیں گئے اُن میں بھی ختنہ کی رسم پائی جاتی ہے اور اُن کی روایات کے مطابق بھی حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے ذریعہ سے یہ رسم اُن میں قائم ہوئی.بائبل کے متعلق تو یہ جدید محقق کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ ؑ نے اُن کو ختنہ کی تعلیم دی کیونکہ وہ مصری تھے اور جب ختنہ کی تعلیم ان میں آ گئی تب بنی اسرائیل نے اس تعلیم کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ ا لسلام کی طرف بھی منسوب کر دیا.مگر یہ لوگ عرب کے متعلق کیا کہیں گے.عربوں کو تو نہ اسرئیلیوں کی تاریخ سے کوئی دلچسپی تھی نہ موسیٰ علیہ ا لسلام سے ان کو کوئی ہمدردی تھی بلکہ وہ تو اسماعیل علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اسحاق علیہ ا لسلام کی وجہ سے اسرائیلیوں سے عناد رکھتے تھے اور اسرائیلی اُن سے خار کھاتے تھے.اُن میں بھی اس رسم کا ہونا اور اُن کا بھی اس رسم کا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہماا لسلام کی طرف منسوب کرنا صاف بتاتا ہے کہ ختنہ کی رسم حضرت ابراہیم علیہ ا لسلام کی معرفت چلی.اور حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو مصری قرار دینے والے محقّق در حقیقت ایک خطرناک غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں.عربوں میں ختنہ کا رواج مدّت سے چلا آتا ہے.چنانچہ اس کی شہادت ’’ فلاس ٹارگی اس ‘‘ بھی دیتا ہے جو مسیح سے ۳۴۲ سال پہلے گزراہے ( دیکھو جیوئش انسا ئیکلو پیڈیا زیر لفظ Circumcision in ethnography) مگر سب سے بڑی شہادت خود عربوں کی قومی شہادت ہے خواہ وہ مسلم تھے یا غیر مسلم.علاوہ ازیں جیوئش انسائیکلو پیڈیا والا لکھتا ہے کہ ختنے کی رسم علاوہ یہودیوں اور مسلمانوں کے اور قوموں میں بھی پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہے چنانچہ ایبے سینین عیسائی بھی ختنہ کراتے ہیں.افریقہ کے وحشی قبائل میں تو یہ رسم اتنی وسیع ہے کہ جیوئش انسائیکلوپیڈیا کے بیان کے مطابق اُن قبائل کا نام لینا آسان ہے جو ختنہ نہیں کراتے بہ نسبت اُن قبائل کے جو ختنہ کراتے ہیں.اسی طرح آسٹریلیا کے پُرانے قبائل بھی ختنہ کراتے تھے جن کاکو ئی تعلق مصر سے ثابت نہیں ہو سکتا.( دیکھو ٹرائبزآف سنٹرل آسٹریلیا مصنّفہ سپنسر اینڈگلن صفحہ ۳۲۳) امریکہ میں بھی کیا شمالی اور کیا جنوبی اور کیا وسطی یہ رسم پائی جاتی تھی ( جیوئش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Circumcision) اِن حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف مصریوں میں اس رسم کا پایا جانا غلط خیال ہے اگر باوجود مصر سے تعلق نہ رکھنے کے افریقہ کے اکثر قبائل میں.آسٹریلیا کے قبائل میں.شمالی جنوبی اور وسطی امریکہ کے قبائل میں اور عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا تو اس بات کے ماننے میں کیا مشکل ہے کہ اسرائیلی بھی ختنہ کرایا کرتے تھے.حق یہ ہے کہ مصر میں ختنے کا پرانے سے پرانا ثبوت ایک مصری بادشاہ کی ممیّ سے جس کا نام ایمن این ہب AMEN-EN-HEBتھا ملتا ہے.اس بادشاہ کا زمانہ ۱۶۱۴ قبل مسیح سے ۱۵۵۵ قبل مسیح تک تھا.
Page 73
(دیکھو جیوئش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Circumcisionبحوالہ آر چِوْفورانتھر ARCHIVFUR ANTHERصفحہ۱۲۳ ) اور یہ زمانہ حضرت یوسف علیہ ا لسلام اور ان کے خاندان کی مصر میں ہجرت کے بعد کا ہے.غرض چونکہ اس حوالہ سے ثابت ہوتا ہے کہ مصر میں ختنے کا قدیمی ثبوت حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام سے صرف دو سو سال قبل ملتا ہے ہم آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ ا لسلام کو مصر کے بادشاہوں کا خاص قُرب حاصل ہو گیا تھا ان کی تعلیم کے ماتحت مصر کے بادشاہوں اور ان کے گِردوپیش کے اُمراء میں ختنہ کا رواج شروع ہو گیا تھا چنانچہ مصری علوم کے محقّقین کی عام رائے بھی یہی ہے کہ مصر میں ختنے کا رواج زیادہ تر بادشاہوں اور پادریوں میں تھا.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری ثابت کرنے کی چوتھی دلیل کا ردّ کہ آپ کے مذہب میں بعث بعد الموت کا ذکر نہیں اس لئے آپ مصری ہیں حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے مصری ہونے کے حق میں چوتھی دلیل یہ دی گئی ہے کہ عمون ہوتپ کے مذہب میں بعث بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں.اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے مذہب میں بھی بعث بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں.اس دلیل میں دو بڑی خامیاں ہیں.اوّل خامی تو یہ ہے کہ عمون ہوتپ کا سارا مذہب معلوم نہیں.اس نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی.اگر چھوڑی ہے تو وہ موجود نہیں اور نہ اُس نے کوئی جماعت چھوڑی ہے پھر یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ عمون ہوتپ کے مذہب میں اس تعلیم کا ذکر نہیں.جب عمون ہوتپ نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی تو کیونکر معلوم ہوا کہ اس کی تعلیم میں بعث بعد الموت کا کوئی ذکر نہیں تھا.کتاب نہ چھوڑی ہوتی جماعت ہی چھوڑی ہوتی تو ہم اس جماعت کے اقوال سے اِس کا اندازہ لگا سکتے مگر ایسی کوئی جماعت بھی عمون ہوتپ نے نہیں چھوڑی.پس یہ کہنا کہ اس کی تعلیم میں یہ بات نہ تھی ایک غیر معقول بات ہے.دوسرے ان لوگوں نے یہ بھی ثابت نہیںکیا کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی تعلیم میں بعث بعد الموت کا ذکر نہیں پایا جاتا.واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی تعلیم میں یہ ذکر پایا جاتا ہے اسی طرح اُن کے تابع نبیوں کی تعلیم میں بھی یہ ذکر پایا جاتا ہے.چنانچہ ذیل میں دو حوالے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام اور حضرت داؤد علیہ ا لسلام کے درج کئے جاتے ہیں.تورات میں لکھا ہے اﷲ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام سے کہا.’’ اور اس پہاڑ پر جس پر توُ جاتا ہے مر جا اور اپنے لوگوں میں شامل ہو جیسے تیرا بھائی ہارون حوُر کے پہاڑ پر مر گیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا.‘‘ ( استثنا باب ۳۲.آیت ۵۰)
Page 74
اسی طرح حضرت داؤد علیہ ا لسلام فرماتے ہیں.’’ اُن لوگوں سے اے خداوند جو تیرے ہاتھ میں دنیا کے لوگوں سے جن کا بخرہ اِسی زندگانی میں ہے اور جن کے پیٹ تو اپنی نہانی چیزوں سے بھرتا ہےان کی اولاد بھی سیر ہوتی اور وَے اپنی باقی دولت اپنے با ل بچوںکے لئے چھوڑ جاتے ہیں.پرمیں جو ہوں صداقت میں تیرا مُنہ دیکھوں گا اور جب میں تیری صورت پر ہو کے جاگوں گا تو میں سیر ہوؤں گا.‘‘ ( زبور باب۱۷ آیت ۱۴و۱۵) ان حوالوں سے صاف ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام بعث بعد الموت کے قائل تھے اور تورات میں اس کا ذکر موجود ہے.حضرت داؤد علیہ ا لسلام بھی اس کے قائل تھے اور زبور میں اس کا ذکر موجود ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عہدنامہ قدیم میں بعث بعد الموت پر اس قدر زور نہیں دیا گیا جیسا کہ زرتشتی مذہب یا اسلام میں دیا گیا ہے یا ہندو مذہب میں دیا گیا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی لوگ بہت ہی دنیادار تھے.جب تورات حوادثِ زمانہ سے مٹی اور یہودیوں نے پھر دوبارہ اُس کو جمع کیا تو انہوں نے تعہد کر کے اُن پیشگوئیوں کو تو جمع کر لیا جو دُنیوی ترقی کے متعلق تھیں لیکن اُن امور کی چنداں پر وانہ کی جن سے اُن کو زیادہ دلچسپی نہیں تھی.اس طرح کئی حِصّے رہ گئے جن میں سے ایک بعث بعد الموت کا بھی حصّہ تھا مگر باوجود اس کے جیسا کہ مَیں نے بتایا ہے اب بھی بعث بعد الموت کا ذکر تورات اور دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں پایا جاتا ہے.کیا موسیٰ علیہ السلام کا سؤر کو حرام قرار دینا مصری تعلیم کے زیراثر تھا؟ پانچویں دلیل یہ دی گئی ہے کہ سؤر بنی اسرائیل میں حرام ہے اور یہی بات مصری تعلیم میں پائی جاتی ہے اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ یہ استدلال ناواقفیت کا نتیجہ ہے.یہ خیال کہ مصری لوگوں میں سؤر حرام تھا درست نہیں.جو کچھ مصری تعلیم کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مصری لوگ سؤر کے گوشت کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے لیکن اس کی حرمت کا ثبوت نہیں ملتا.( انسائیکلوپیڈیا ببلیکا زیر لفظ Swine a scared animalبحوالہ کتاب ایجپٹ (EGYPT) صفحہ ۴۴۱ مصنّفہ ارمن (ERMAN) بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ بات ہے کہ مصر میں بعض جگہ پر سؤر پالے جاتے تھے چنانچہ انسائیکلو پیڈیا ببلیکا کے اِسی صفحہ پر رینی (RENNI) کے متعلق لکھا ہے کہ اُس کے مال میں تین سو سؤر بھی تھے اور یہ رینی الکاب (EL-KAB)کے مندر کے دیوماکاکاہن تھا اور ہیروڈوٹس (HERODOTUS) لکھتا ہے کہ سی لین ( SALENE)اور ڈایونیسس (DIONYSUS)یعنی اوسی رس(Osiris)کے ناموں پر سؤروں کی قربانی کی جاتی تھی اسی طرح پاہیری (PAHERI)جو شاہانِ مصری کے اٹھارویں حاکم خاندان کا بادشاہ تھا اس کی
Page 75
قبر پر سُؤروں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں.( یہ تمام حوالے انسائیکلوپیڈیا ببلیکا زیر لفظ Swine a scared animal پر دیکھیں) اسی طرح پروفیسر اڈولف لاڈز (Adolphelods)جو پیرس کی ساربان (Sorbonne)یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اپنی کتاب اسرائیل میں لکھتے ہیں کہ مصر میں عام طور پر تو سؤر کے گوشت سے پرہیز کیا جاتا تھا لیکن خاص خاص چاندوں کی چودھویں تاریخوں پر ’’ سی لین ‘‘ اور ’’ ڈایونیسس‘‘ کے مندروں پر اُس کی قربانی کی جاتی تھی اور اُن کے پجاری اُسے کھاتے تھے ( کتاب اسرائیل صفحہ ۲۴۸).پس یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام نے چونکہ سُؤر کے کھانے سے روکا اس لئے وہ مصری تھے درست نہ ہوا کیونکہ خود مصریوں میں سؤر کی پُوری ممانعت نہیں اور جن قبائل میں ممانعت ہے ان میں بھی اس کو گندہ قرار دے کر ممانعت نہیں بلکہ ایک مقدّس جانور قرار دے کر ممانعت ہے تبھی تو خاص خاص تہواروں پر مندروں میں اس کی قربانی کی جاتی تھی اور پجاری لوگ اس کو کھاتے تھے.سؤر کو پاکیزہ جانور قرار دینا صرف میرا قیاس نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے چنانچہ انسائیکلو پیڈیا ببلیکا والا لکھتا ہے کہ ایشیائے کوچک.یونان اور اٹلی میں سؤر کو خاص عزت حاصل تھی.اسی طرح پروفیسر لاڈز (LORDS) لکھتے ہیں کہ سؤر بنی اسرائیل کے بہت سے ہمسائیوں کے نزدیک ایک مقدّس جانور تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پر خدا تعالیٰ کی تقدیس نازل ہوئی ہے بابل کے لوگوں میں نَنِیب(NINIB)کی وجہ سے اور شامی لوگوں میں تمُوز (TAMMUZ)کی وجہ سے یہ مقدّس سمجھا جاتا تھا چنانچہ شامیوں میں تمُوز کے نام جو مہینہ مقرر کیا گیا تھا اس کا نام خَنْزیُرو یعنی خنزیر (سُؤر) تھا (دیکھو کتاب اسرائیل صفحہ ۲۴۸ بحوالہ ڈی کا ٹلن شرفٹن اُنڈڈاس آ لٹے ٹیسٹامینت مصنّفہ ہائین رچ زمَّرن اور ہیوگوو نکلر) اِن حولوں سے مزید تقویت اِس خیال کو پہنچتی ہے کہ مصری لوگوں میں خنزیر کے ذبیحہ سے اجتناب اُس کی تقدیس کی وجہ سے تھا نہ کہ اُسے بُرا سمجھنے کی وجہ سے لیکن جیسا کہ بائبل سے ظاہر ہے یہود میں اُسے بُرا اور گندا قرار دیا گیا ہے پس سؤر کی حرمت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام مصری تھے کسی صورت میں بھی درست نہیں ہو سکتا.اس دلیل کا ردّ کہ چونکہ حضرت موسیٰ اچھی طرح کلام نہیں کر سکتے تھے اس لئے آپ مصری تھے چھٹی دلیل حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے مصری النسل ہونے کی تائید میں یہ دی جاتی ہے کہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح کلام نہیں کر سکتے تھے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ غیر نسل سے تھے اور یہودیوں کی زبان میں اُن سے کلام نہیں کر سکتے تھے.
Page 76
جہاں تک اس امر کا تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام صفائی کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے تھے وہ تو ایک حد تک درست ہے بائبل میں بھی یہ ذکر ہے اور قرآن کریم نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے خروج باب۳ میں لکھا ہے.’’ پس اب تو جامیںتجھے فرعون پاس بھیجتا ہوں.میرے لوگوں کو جو بنی اسرائیل ہیں مصر سے نکال.موسیٰ نے خدا کو کہا ،مَیں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالوں.‘‘ (خروج باب۳آیت۱۰،۱۱) اس کے بعد ان مختلف ہدایتوں کا ذکر ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو ملیں پھر اس سلسلۂ کلام کے آخر پر یُوں کہا گیا ہے کہ:.’’ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ اے میرے خداوند مَیں فصاحت نہیں رکھتا نہ تو آگے سے اور نہ جب سے کہ تو نے اپنے بندے سے کلام کیا اور میری زبان اور باتوں میں لکنت ہے تب خداوند نے اُسے کہا.کہ آدمی کو زبان کس نے دی اور کون گونگا یا بہرایا بینایا اندھا کرتا ہے کیا مَیں نہیں کرتا جو خداوند ہوں.پس اب تو جا اور مَیں تیری بات کے ساتھ ہوں اور تجھ کو سکھاؤں گاجو کچھ توکہے گا.‘‘ (خروج باب۴ آیت۱۰ تا ۱۲) قرآن کریم میں آتا ہے وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰۤى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.قَوْمَ فِرْعَوْنَ١ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ.قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ.وَ يَضِيْقُ صَدْرِيْ وَ لَا يَنْطَلِقُ لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ.(الشعراء :۱۱تا۱۴) یعنی یاد کرو جبکہ تیرے رب نے موسیٰ سے کہا کہ ظالموں کی قوم یعنی فرعون کی قوم کے پاس جا اور انہیں کہہ کہ کیا وہ تقویٰ اختیارنہیں کریںگے.موسیٰ علیہ ا لسلام نے کہا.اے میرے رب مَیں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ میری تکذیب کریںگے اور اُن کی تکذیب کے خیال سے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان چلتی نہیں.پس نبوت کو ہارون کی طرف بھیجئے.بائبل اور قرآن کے ان حوالوں سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی زبان میں کوئی نقص تھا اور انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ میری زبان نہیں چلتی اس لئے میری جگہ کِسی اَور کو بھیجئے.لیکن اس کے ساتھ ہی بائبل اور قرآن دونوں کے حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام نے اپنی زبان نہ چلنے کا عذر اس وقت کیا ہے جب اُنہیں فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے.اب دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو ہم حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے اس عذرکے یہ معنے کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی یا اعصابی طور پر کچھ ایسی کمزوری تھی کہ جب اُنہیں جوش آجاتا تھا تو وہ صفائی سے اپنا مافی الضمیر ادا نہیںکر سکتے تھے اور
Page 77
الفاظ یا حروف کو حذف کر دیتے تھے اور یا ہم یہ معنے کریں کہ جس قوم کو مخاطب کرنے کا حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو حکم دیا گیا تھا اس کی زبان میں وہ اچھی طرح کلام نہیں کر سکتے تھے.اگر اوّل الذکر معنے لئے جائیں تو پھر یہ استدلال کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام مصری تھے بالبداہت باطل ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ زبان میں لکنت کا ہونا یا کسی شخص میں ایسی اعصابی کمزوری کا پایا جانا کہ جوش والی تقریر میں عبارت اُس کے قابو میں نہ رہے.یہ مصریوں کا خاصہ نہیں.بنی اسرائیل میں بھی یہ مرض ایسی ہی پائی جا سکتی ہے جیسا کہ مصریوں یا کسی اور قوم میں.اور اگر دوسرے معنے کئے جائیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے عذر سے مراد زبان کا نہ جاننا ہے تو پھر تو یہ اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام مصری نہ تھے کیونکہ بائبل بھی یہی بیان کرتی ہے اور قرآن کریم بھی یہی بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر اُس وقت پیش کیا ہے جب اُنہیںفرعون کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے.کیا کوئی عقلمند یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ مصری موسیٰ مصری فرعون کو تبلیغ کرنے کا حکم سُن کر یہ عذر کرے گا کہ مجھے مصری زبان نہیں آتی.اگر وہ مصری تھے تو اُن کو تو وہ زبان آتی تھی جو فرعون بولتا تھا.پس اگر حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے عذر کی یہ تشریح کی جائے کہ وہ اُس زبان کے نہ جاننے کا عذر کرتے ہیں جس سے اُن کا مخاطب واقف ہے تو پھر اس سے یقینی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اسرائیلی تھے.چونکہ فرعون کو تبلیغ کرنے کا اُنہیں حکم دیا گیااور وہ فرعون کی زبان کو اچھی طرح نہ سمجھتے تھے انہوں نے خدا تعالیٰ سے یہ عذر کیا کہ جس شخص کو تبلیغ کرنے کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں اُس کی زبان اچھی طرح نہیں جانتا یعنی مَیں عبرانی زبان کا ماہر ہوں اور وہ مصری زبان بولنے والا ہے.پس یہ استدلال نہایت ہی بودہ، نہایت ہی کمزور اور قلّتِ تدبّر کا نتیجہ ہے.خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم اور بائبل کا دعویٰ کہ موسیٰ علیہ ا لسلام بنی اسرائیل میں سے تھے صحیح اور محقّقین جدید کا یہ دعویٰ کہ وہ مصری تھے نہایت غلط اور خلافِ عقل ہے.حق یہ ہے کہ کوئی ثبوت اِس بات کی تائید میں نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام اسرائیلی نہ تھے لیکن بیسیوں ثبوت اس بات کی تائید میں ہیں اور پیش کئے جا سکتے ہیں اور بعض اوپر پیش کئے گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام اسرائیلی تھے.اَلْکِتاب.وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ … الخ کی تشریح فرماتا ہے ہم نے اِس جگہ پر موسیٰ کو کچھ احکام دیئے.کتاب کے معنی جیسا کہ حلِّ لغات سورہ بقرہ آیت نمبر۳میں بتایا گیا ہے مفروضات کے ہوتے ہیں یعنی فرض کی گئی باتیں.پس اَلْکِتَاب سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ ا لسلام کو وہاں بعض نہایت ہی تاکیدی احکام عطا فرمائے.قرآن مجید کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیئے جانے پر ریورنڈ ویری کا
Page 78
اعتراض اور اس کا جواب ریورنڈویری نے اپنی تفسیرمیں اِس آیت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہاں ہمیں محمد( صلی اﷲعلیہ و آلہٖ وسلم ) کی یہودی تاریخ سے ناواقفیت کی ایک مثال ملتی ہے جیسا کہ اور بھی کئی مثالیں اِس سورۃ میں ہمیں مِلتی ہیں اور وہ مثال یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو تورات اس پہاڑ پر دی گئی تھی.حالانکہ وہاں ان کو صرف الواح ملی تھیں پس قرآن کریم کا بیان ایک اسرائیلی تاریخ سے ناواقف انسان کا بیان ہے.میرے نزدیک پادری صاحب کو (اوّل) بائبل پر حد سے زیادہ حسن ظنّی معلوم ہوتی ہے جس کی وہ مستحق نہیں ( دوم) قرآنِ کریم سے اُن کو اتنی دشمنی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اُس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے.وہ اپنی نجات کے لئے اُس پر اعتراض کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں.اُن کا بغیر کسی بیرونی شہادت کے بائبل کے بیان کو صحیح قرار دینا نہایت خلافِ عقل بات ہے.بائبل کے تو باب باب کی خود عیسائی مصنّفین نے ایسی دھجیاں اُڑائی ہیں کہ اس کی کسی بات کی تصدیق بیرونی شہادت کے بغیر ناممکن ہے.پادری صاحب کہتے ہیں بائبل سے ثابت ہے کہ طُور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو الواح ملی تھیں.چونکہ قرآن اس کے خلاف کہتا ہے اس لئے قرآن جھوٹا ہے اور وہ (نعوذ باﷲ ) ایک جاہل انسان کی تصنیف ہے مگر پادری ویری صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ خو د اُن کے ہم مذہب جیسا کہ ہم اوپر بتا آئے ہیں اوّل تو موسیٰ علیہ ا لسلام کے ہی منکر ہیں.پھر اگر موسیٰ علیہ ا لسلام کے قائل ہیں تو وہ اسے ایک مصری نثراد انسان بتاتے ہیں اور بعض اُن میں سے بنی اسرائیل کے مصر جانے کے ہی قائل نہیں کُجا یہ کہ وہاں سے خروج کے قائل ہوں.پھر جس طُور کے متعلق پادری ویری صاحب کا خیال ہے کہ وہاں دو الواح ملی تھیں.محقّقین جدید اوّل تو اِس طُور کے ہی منکر ہیں اور اگر اسے مانتے ہیں تو مصر اور عرب اور شام کے درمیانی علاقہ میں مختلف مقامات پر اس کی تعیین کرنا چاہتے ہیں.بائبل کے جو بیانات تاریخ کے رو سے اتنے مجروح ہیں اس کے متعلق یہ کہنا کہ یہ محمدرسول اﷲ صلی اﷲعلیہ و آلہٖ وسلم کی ناواقفیت ہے کہ انہوں نے بائبل کے خلاف بات لکھ دی صرف اتنا ہی ظاہر کرتا ہے کہ پادری ویری صاحب کو نہ بائبل کا علم ہے اور نہ اُن تاریخوں کا جو بائبل کے متعلق نئے انکشاف کی بناء پر لکھی گئی ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ طوُر پر ملا وہ صرف دس احکام تھے قرآن کریم کے متعلق اُن کو جو تعصّب ہے اُس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ قرآن کریم میں طُور پر ساری بائبل کے اُترنے کا کہیں ذکر نہیں بلکہ بائبل کے بیان کے موافق جسے ویری صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے بعض احکام اور الواح کے اُترنے کا ہی ذکر ہے.
Page 80
پردوں اور دروازوں کے پردوں کے بنائے جانے کے متعلق تعلیم ہے.باب ۲۷ میں سوختنی قربانی کا مَذْبَح اور اس کے اسباب.مسکن کے صحن.اس کے پردوں اور ستونوں اور چراغ کے تیل کی بابت احکام دیئے گئے ہیں.باب ۲۸ میں ہارون علیہ ا لسلام اور اُس کے بیٹوں کو کہا نت کے لئے مخصوص کئے جانے.پاک لباس بنانے کا حکم دیئے جانے.افود.عدل کی چپراس.اور یَم و تمیم کے متعلق احکام اور پگڑیوں اور منقّش کُرتوں اور ہارون علیہ ا لسلام کے بیٹوں کے لباس کے متعلق احکام دیئے گئے ہیں.باب ۲۹ میں کاہن کے مقدّس کرنے کے متعلق قربانی کی رسوم.دائیم سو ختنی قربانی کی رسوم.اور خدا کا بنی اسرائیل کے درمیان رہنے کا وعدہ بیان کیا گیا ہے.باب ۳۰ میںبخُورکے مَذبح خانوں کے فدیہ.برنجی حوض.مساحت کے مقدّس تیل اور بخور کے بنانے کی ترکیبیں بیان کی گئی ہیں اور باب ۳۱ میں کچھ اور ہدائتیں دینے کے بعد ان کے ساتھ دو لوحیں سپرد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے.اتنے بابوں کی تعلیم کو پادری ویری صاحب کس طرح بھول گئے.بارہ بابوں میں ان احکام کا ذکر ہے جو طُور پر حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو دیئے گئے اور اُن میں سے صرف نصف میں ( دس احکام) اور لوحوں کا ذکر ہے.مگر باوجود اِس کے پادری صاحب کہتے ہیں کہ وہاں لوحوں کے سوا کچھ نہیں مِلااور قرآن کریم کا یہ کہنا کہ وہاں لوحوں کے سوا کچھ اور بھی ملا تھا قرآن کریم کی ناواقفیت کا ثبوت ہے.الکتاب کے معنی باقی رہا پادری صاحب کا یہ کہنا کہ قرآن کریم کے نزدیک ساری تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر دی گئی تھی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے.اَلْکِتَاب کے معنی ساری کتاب کے نہیں بلکہ الکتاب کے معنے کچھ حصہ کتاب کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ قرآنِ کریم میں ایک معمولی خط کا نام بھی کتاب رکھا گیا ہے.سورۂ نمل میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.حضرت سلیمان علیہ ا لسلام نے سبا کی ملکہ کو ایک خط لکھا.اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ ا لسلام نے اپنے پیغامبر کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا.اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ.قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ.اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَ اْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ.(النّمل :۲۹تا۳۲) یعنی توُیہ میری کتاب لے جا اور سبا کے لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دے.پھر پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائیو اور دیکھیو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں.جب پیغامبر نے اس کے مطابق عمل کیا اور وہ خط سبا والوں کے سامنے پیش کر دیا تو سبا کی ملکہ نے کہا اے میرے سردارو میرے سامنے ایک معزّز کتاب پیش کی گئی ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون یہ ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.مجھ پر ظلم نہ کرو.اور فرمانبردار بن کر میرے پاس آ جاؤ.یہاں کتاب صرف
Page 81
ڈیڑھ یا دوسطر کے ایک خط کا نام رکھا گیا ہے.پس محض کتاب کے لفظ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس سے مراد ساری تورات ہے صرف اس خواہش کا نتیجہ ہے کہ کسی طرح قرآن کریم پر اعتراض کیا جائے خواہ سچائی کو فائدہ پہنچتاہو یا نقصان.اَلْفُرْقَانُ کے متعلق ریورنڈ ویری کا اعتراض کہ یہ لفظ شامی ہے فرقان کے متعلق ریورنڈویری نے اپنی تفسیر میں رومن اُردو قرآن کے حوالہ سے جو ایک عیسائی کی مختصر تفسیر ہے لکھا ہے کہ یہ لفظ شامی زبان سے مستعار لیا گیا ہے.معلوم ہوتا ہے کہ محمد ( صلی اﷲ علیہ وسلم) افرائیم شامی کی تفسیر بائبل سے واقف تھے جس میں متواتر بائبل کو فرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے.پادری ویری صاحب اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ لفظ شامی زبان سے لیا گیا ہے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہ ٖوسلم کوکسی شامی یا عبرانی عیسائی کتاب کی واقفیت تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان کردہ واقعات تاریخ کلیسیا کے واقعات سے نہایت ہی مختلف ہیں پس وہ صرف سُنی سُنائی حکایات پر مبنی کہے جا سکتے ہیں.رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کا کسی شامی کتاب سے واقف ہونا یا نہ ہونا تو ایک ایسا سوال ہے جس کا اس موقع سے کوئی تعلق نہیں اور نہ کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم کر سکتا ہے.رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم صرف چند ہفتوں کے لئے شام میں ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ گئے تھے.اس عرصہ میں آپ کا شامی زبان سیکھ جانا اور اس کے لٹریچر کا مطالعہ کر لینا یہ صرف ایک فاترالعقل انسان کا ہی خیال ہو سکتا ہے کوئی معقول آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا.انگریز چالیس چالیس سال تک ہندوستان میں رہتے ہیں مگر پھر بھی ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جو اُردو زبان کو پڑھ سکتا ہو.ورنہ تحریری زبان تو الگ رہی بولنے والی زبان سے بھی وہ بالکل کورے ہوتے ہیں پھر اس تجربہ کے ہوتے ہوئے کِسی مصنّف کا یہ کہنا کہ صرف چند ہفتوں کے اندر اندر رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے اپنے تجارتی کاموں کے علاوہ شامی زبان بھی سیکھ لی تھی اور نہ صرف شامی زبان سیکھ لی تھی بلکہ شامی زبان کے لٹریچر سے بھی واقفیت حاصل کر لی تھی صرف اُس تعصّب کو ظاہر کرتا ہے جو مسیحی اقوام کے دلوں میں رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے متعلق پیدا ہو چکا ہے.اس بات کا ردّ کہ فرقان شامی لفظ نہیں باقی رہا فرقان کا شامی لفظ ہونا یہ بھی عربی زبان سے ناواقفیت کی علامت ہے.تعجب ہے کہ وہ لوگ جو عربی زبان سے کوئی َمس نہیں رکھتے وہ قرآن کریم کی تفسیریں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں جو عربی زبان کا بہترین نمونہ اور اُس کی تمام خوبیوں کا حامل ہے.اس بات کا ثبوت کہ فرقان عربی لفظ ہے فُرْقَان کا لفظ درحقیقت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے بہت
Page 82
سے صیغے مختلف شکلوں میں عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں.اِس آیت سے پہلے ہی وَاِذْ فَرَقْنَابِکُمُ الْبَحْرَ آچکا ہے.اسی طرح عربی زبان میں فَرَقَ.فَرَّقَ.فَارَقَ.اَفْرَقَ.تَفَرَّقَ.تَفَارَقَ.اِنْفَرَقَ.اِفْتَرَقَ.فَارُوْقٌ.فَرَاقٌ.فَرْقٌ.فَرُّوْقٌ.فُرَقَانٌ.فُرْقٌ.فِرْقٌ.فَرَقٌ.فَرِیْقٌ.فَرْقَاءُ.فِرْقَۃٌ.فَرُوْقٌ.فَرِیْقَۃٌ.اَفْرَقُ.تَفَارِیْقُ.مَفْرَقٌ.مَفْرِقٌ.مُفْرِقٌ.مُنْفَرَقٌ.مُفَرِّقٌ وغیرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سب کے سب فرقان کے مادے سے ہیں.اگر یہ لفظ شامی زبان سے مستعار لیا گیا ہے تو تمام کے تمام الفاظ عربی زبان میں کہاں سے آگئے اور اگر یہ الفاظ عربی زبان کے ہیں تو اس مادے کا جو مصدر ہے وہ شامی کس طرح ہو گیا.ہاں ایک صورت ہوسکتی تھی اور وہ یہ کہ فرقان کا وزن عربی زبان کے اَوزان میں سے نہ ہوتا اِس صورت میں بے شک کہا جا سکتا تھا کہ گو یہ مادہ عربی زبان کا ہے مگر چونکہ فرقان کا وزن عربی میں مستعمل نہیں اس لئے یہ لفظ شامی زبان سے لیا گیا ہے.لیکن ہم دیکھتے ہیں فرقان کا وزن عربی زبان میں بکثرت استعمال ہوا ہے چنانچہ سُبْحَان خدا تعالیٰ کا نام ہے قُرْاٰن قرآن کریم کا دوسرا نام ہے.نُعْمَان فقہ کے مشہور امام حضرت امام ابوحنیفہؒکے نام کا جزو ہے.کُفْرَان کفر کو کہتے فُقْدَان کے معنے غائب ہو جانے کے ہیں پس یہ وزن بکثرت عربی ز بان میں استعمال ہوتا ہے اور اس وزن کے سینکڑوں الفاظ عربی زبان میں پائے جاتے ہیں پس جبکہ فرقان کا مادہ بھی عربی زبان میں مختلف شکلوں میں کثرت سے استعمال میں آتا ہے اور فرقان کا وزن بھی عربی زبان کا وزن ہے اور اس قسم کے سینکڑوں الفاظ عربی زبان میں پائے جاتے ہیں اسے شامی کہنا ناواقفیت اور جہالت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے مگر میں اس سے بڑھ کر ایک اور ثبوت اس بات کا دیتا ہوں کہ یہ لفظ عربی کا ہے بلکہ اس مادے کو پورے طور پر صرف عربی نے ہی استعمال کیا ہے اور شامی اور عبرانی زبانیں جو عربی کی فرعیں ہیں اگر اُن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے تب بھی وہ اس پوری حکمت اور شان کا حامل نہیں جس حکمت اور شان کا حامل یہ عربی لفظ ہے.یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں صرف لفظ کے معنے نہیں ہوتے بلکہ لفظ جن حروف سے مرکّب ہوتا ہے اس کے اصل معنوں پر وہ دلالت کرتے ہیں چنانچہ حروف کے مقام اور مختلف حروف کے مشابہ حروف کے اندر بھی معنوں کا ایک تسلسل پایا جاتا ہے مثلاً ایک لفظ ف ر ق سے بنتا ہے جیسے فُرْقَان تو ایک تو اس لفظ کے مخصوص معنے عربی زبان میں ہوں گے اور ایک معنوں کی فلسفیانہ حکمت ہو گی جو نہ صرف اس لفظ میں پائی جائے گی بلکہ تمام ان الفاظ میں بھی پائی جائے گی جو ف ر ق سے بنے ہوں اور ان میں بھی اصولی طور پر وہی معنے یا اس کے مخالف معنے پائے جا ئیں گے.مخالف معنے بھی ایک مشارکت رکھتے ہیں یعنی ان کی وجہ سے ذہن میں دوسرے معنے آ جاتے ہیں چنانچہ عربی زبان میں بہت سے ایسے لفظ پائے جاتے ہیں جو مخالف معنے
Page 84
فَقْرَاتِ ظَہرکہلاتی ہے کیونکہ وہ بھی ہار کی شکل کی ہی ہوتی ہے یعنی الگ الگ ٹکڑوں کے اندر ایک سفید تاگا گزرتا ہے پھر دوسرا اجتماع ف ر ق کا قَرف اور قَفر کی شکل میں ہو سکتا ہے اِن میں بھی وہی دونوں معنے پائے جاتے ہیں یعنی جدائی اور اتصال کے معنے چنانچہ قَرْفٌ کے معنے چھلکے اُتارنے کے ہوتے ہیں جس میں جُدائی کا مفہوم پایا جاتا ہے اِسی طرح قَرْفٌ کے معنے زخم کو چھیلنے کے ہوتے ہیں.قَرْفٌ کے معنے عیب لگانے کے ہوتے ہیں اور عیب گیری بھی تفرقہ پیدا کرتی ہے اسی طرح اور بھی چند معنے اس کے ہوتے ہیں.مثلاً رشتہ داروں کے لئے مال کمانا اور چیزوں کو آپس میں مِلا دینا اور قَارَفَ کے معنے قریب ہو جانے کے ہوتے ہیں گویا ان معنوں میں بھی افتراق اور اِتصال دونوں معنے پائے جاتے ہیں.اسی طرح قَفْرَ کے معنے کسی کے پیچھے چلنے کے ہوتے ہیں تَفَقَّر کے معنے جمع کرنے اور اَقْفَرَ کے معنے خالی ہو جانے کے ہوتے ہیں اور قَفْرٌ کے معنے جنگل کے ہوتے ہیں.جو آبادیوں میں فاصلہ پیدا کر دیتا ہے اور قَفَارٌ اُس روٹی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سالن نہ ہو.اب رہی ف ر ق کے اجتماع کی تیسری شکل.سو وہ رِفْقٌ اور رقف ہے یعنی ر پہلے ہے اور ف ق یا ق ف بعد میں آتے ہیں.رِفْقٌکے معنے نرمی کے ہیں جو اجتماع کا ذریعہ ہوتا ہے رِفْقٌ کے معنے باندھ لینے کے بھی ہوتے ہیں اور رَفِیْقٌ کے معنے ساتھی کے ہوتے ہیں اور رَفَاقت کے معنے دوستی کے ہوتے ہیں اسی طرح مِرْفَقٌ کہنی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دو ہڈیوں کو مِلاتی ہے.رقف کانپنے کو کہتے ہیں جوڈر کا نتیجہ ہوتا ہے اور فَرَقَ کے ایک معنے بھی ڈر کے بتائے جا چکے ہیں پس ف ر ق سے جتنے الفاظ عربی زبان میں بنتے ہیں ان سب میں اتّصال یا افتراق کے معنے پائے جاتے ہیں.اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ فرقان کا لفظ غیر زبان سے آیا ہے عربی زبان کا لفظ نہیں ہےبلکہ میں تو یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ اشتقاقِ اکبر کے لحاظ سے بھی فرقان کا لفظ عربی ہی ثابت ہوتا ہے یعنی ف ر ق کے مجموعہ میں ہی معنوں کا اشتراک نہیں پایا جاتا بلکہ اُن کے قریب المخارج الفاظ کے معنوں میں بھی فُرْقَان کے ساتھ اشتراک پایا جاتا ہے مثلاً ف کی جگہ واو رکھ دیں ر کی جگہ ل رکھ دیں ق کی جگہ ک رکھ دیں تب بھی بہت سے الفاظ میں معنوں کا اشتراک پایا جائے گا مگر چونکہ یہ تفسیر کی کتاب ہے ادبی کتاب نہیں اس لئے میں اس تفصیل میں پڑنا مناسب نہیں سمجھتا.فرقان کے معنے جیسا کہ حَلِّ لُغَات میں بتایا جا چکا ہے فُرْقَان کے اصلی معنے تو فرق کر دینے یا دو چیزوں میں امتیاز کر دینے کے ہیں.اب رہا یہ سوال کہ اس جگہ پر اسلامی اصطلاح میں فُرْقان کے کیا معنے ہیں.سو یاد رکھنا چاہیئے کہ مختلف مفسّرین نے اس کے مختلف معنے کئے ہیں.تفسیرجریر ، طبری جلد اوّل میں ابوالعالیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا فُرْقَان کے معنے ہیں بِمَا فُرِقَ بِہٖ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ یعنی ایسی چیز جس کے ذریعہ حق اور باطل
Page 85
میں فرق کر دیا گیا ہو.مجاھد کا قول ابنِ جریر نے یہ لکھا ہے کہ فُرْقَان سے مراد کتاب ہی ہے اور اس کے معنے حق اور باطل میں فرق کرنے والے کے ہیں.ابنِ جریر نے حضرت ابن عباس کا یہ قول لکھا ہے کہ فُرْقَان مجموعی نام ہے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کا.ابن زید سے ابنِ جریر نے یہ روایت کی ہے کہ فُرْقَان محمدرسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو بھی ملا اور حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو بھی مِلا.بدر کے موقع پر خدا تعالیٰ نے مشرکوں اور مسلمانوں میں امتیاز کر کے دکھا دیا اور واقعۂ سمندر کے رو سے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے دشمنوں میں فرق کر کے دکھا دیا.علاّمہ قرُطبی لکھتے ہیں بعض لوگوں نے اس آیت کے معنے یہ کئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو تورات دی اور محمد صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو فرقان دیا.اختصار کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم کا نام بیان نہیں کیا لیکن یہ معنے بالبداہت غلط ہیں اسی طرح وہ لکھتے ہیں جن لوگوں نے فرقان کے معنے کتاب کے کئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کتاب کے بعد فرقان کا لفظ تاکید کے لئے استعمال کیا گیا ہے چنانچہ زَجَّاج کا یہی قول ہے اور یہی فَرَّاء نے بھی بیان کیا ہے.بعضوں نے فُرْقانَ کے معنے مصیبت سے نجات کے کئے ہیں.اور اس سے مراد مصر سے نکلنے کو لیا ہے اور ابنِ بحر نے کہا ہےکہ حجت اور بیان اس کے معنے ہیں.بعض نے کہا ہے واؤزائد ہے.اور فُرْقَانکتاب کی صفت ہے.( تفسیر القرطبی زیر آیت ھذا ) کتاب اور فرقان دونوں ایک نہیں ہو سکتے خلاصہ ان حوالوں کا یہ ہے کہ فُرْقَان کے معنے حق و باطل میں تمیز کرنے کے ہیں.آگے اس بات کی تعیین کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی کس چیز کو خدا تعالیٰ نے حق و باطل میں تمیز کرنے والی قرار دیا ہے.اس کے متعلق بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی کتاب کو ہی فرقان قرار دیا گیا ہے.بعض نے غرقِ فرعون کو اور بعض نے مصر سے اُن کے بچ کر نکل آنے کو اس لفظ کا مستحق بتایا ہے.لیکن میرے نزدیک کتاب اور فرقان کو ایک قرار دینا قرآن کریم کے دوسرے مقامات کو مدّنظر رکھ کر کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتا.اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَ ضِيَآءً وَّ ذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ۠ (الانبیاء :۴۹) یعنی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور متقیوں کے لئے نصیحت عطا فرمائی تھی.اس آیت میں فُرْقَان کے دینے میں حضرت ہارون علیہ ا لسلام کو بھی شامل کر لیا گیا ہے.پس فرقان کے معنے تورات کے نہیں لئے جا سکتے.قرآن کریم میں فرقان کے لفظ کا استعمال مختلف معنوں میں قرآن کریم میں فُرْقَان کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے (۱) فُرْقَان کا لفظ قرآن کریم کی نسبت بھی استعمال ہوا ہے جیسے سورۂ فرقان میں اﷲتعالیٰ فرماتا
Page 86
ہے.تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرَا (الفرقان:۲) برکت والا ہے وہ خدا جس نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم پر فُرْقَان اُتارا تاکہ وہ ساری دنیا کے لئے نذیر بنے.اس سے معلوم ہوتا ہے.کہ فُرْقَان قرآن کریم کا نام ہے.اسی طرح قرآن کریم کے متعلق سورۂ بقرہ میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ (البقرہ:۱۸۶)یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اﷲ نے قرآن کریم اُتارا ہے جس قرآن میں ایک تو لوگوں کے لئے ہدایت ہے دوسرے اس میں دلائل ہیں ہدایت کے اور دلائل ہیں فُرْقَان والے.یعنی ایسے دلائل جو حق اور باطل میں تمیز کر دیتے ہیں.اس آیت کے ذریعہ قرآن کریم کو فُرْقَان پر مشتمل بتایا گیا ہے قرآن کریم میں فرقان کے ایک معنی مصیبت اور مشکل سے نجات کے بھی آتے ہیں چنانچہ سورۂ انفال میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا (الانفال:۳۰) اے مومنو اگر تم اﷲ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو تو اﷲ تعالیٰ تمہارے لئے ہر مصیبت اور مشکل سے بچنے کا راستہ نکالتا رہے گا.ان آیات پر غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ درحقیقت فُرْقَانکے معنے حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز کے ہی ہیں.ہر نبی کو فرقان دیا جاتا ہے اگر اﷲ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے فُرْقَان کا وعدہ کیا ہے تو اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ مشکلات کے وقت ان کو ایسی تمیز بخش دے گا کہ وہ صحیح راستہ معلوم کرنے کے قابل ہو جائیں گے.اگر حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو فُرْقَان ملا تھا تو اس کے معنے بھی یہی ہیں کہ اُنہیں کوئی ایسی چیز ملی تھی جس سے وہ اپنے دوست اور دشمن اور حق اور باطل میں تمیز کر سکتے تھے اور اگر رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو کوئی چیز ایسی ملی تھی جس کو ہم فُرْقَان کہہ سکتے ہیں تو اس کے معنے بھی یہی ہیں کہ آپ کو ایسی چیز ملی تھی جس سے آپؐ اور آپؐ کے اتباع حق اور باطل میں تمیز کر لیتے تھے اور آپؐ کے مخالف اگر چاہتے تو اس کی مدد سے حق کو سمجھ سکتے تھے.پس کوئی وجہ نہیں کہ فُرْقَان کے معنے محدود کئے جائیں اور اسے بدر کی جنگ یا سمندر سے بچ نکلنے کے معجزوں تک محدود کیا جائے.بیشک بدر کی جنگ کو بھی فرقان کہا گیا ہے اور بیشک سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کا بچنا بھی ایک فرقان تھا مگر صرف یہی دو چیزیں رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو نہیں ملیں.ان کے علاوہ بیسیوں معجزات حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کو اور ہزاروں معجزات رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلّم کو ملے تھے.پس جہاں کسی خاص معجزے کا نام قرآن کریم نے فُرْقَان رکھا ہے (جیسے بدر کے معجزہ کا) وہاں تو ہم اُس کے وہ خاص معنے کریںگے لیکن جہاں کسی خاص معجزے کا ذکر نہیں کیا وہاں ہم فُرْقَان کے معنوں کو محدود نہیں کر سکتے.اصل
Page 87
بات یہ ہے کہ ہر نبی کو اﷲ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی شریعت دی جاتی ہے خواہ وہ نئی ہو یا پرانی ( یعنی سابق نبی کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے) اسی طرح فُرْقَان دیا جاتا ہے.یعنی ایسے نشانات دیئے جاتے ہیں جن کے ذریعہ حق اور باطل میں تمیز ہو سکے اور یہ فرقان ہی ان کی سچائی کو پہچاننے کا حقیقی ذریعہ ہوتا ہے.ہر زمانہ میں لوگوں نے اِس نکتہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سچّے نبیوں کو ماننے سے اِنکار کیا ہے یا جھوٹے نبیوں کے فریب میں آئے ہیں.اﷲ تعالیٰ کے انبیاء کی صداقت کِسی ایک چیز پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ انہیں بیسیوں قسم کے دلائل دیئے جاتے ہیں جو بحیثیت مجموعی ان کی سچائی یا ان کے درجہ کی بلندی پر گواہ ہوتے ہیں بعض لوگ صرف چند خواب یا الہام دیکھ کر اپنے آپ کو مامور قرار دینے لگ جاتے ہیں حالانکہ خوابیں اور الہام خیالی بھی ہو سکتے ہیں بیماریوں کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں.طبعی بھی ہو سکتے ہیں.شیطانی بھی ہو سکتے ہیں اور رحمانی بھی ہو سکتے ہیں.صرف کِسی خواب یا الہام کا سچا ہو جانا بھی اُس کے رحمانی ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا کیونکہ طبعی اور خیالی باتیں بھی کئی دفعہ پوری ہو جاتی ہیں.انبیاء کے الہام تو اپنے اندر ایک خاص شان رکھتے ہیں.ان کے اندر وسعت ہوتی ہے.زمانہ کے مفاسد کا علاج ہوتا ہے اور زمانہ کے حالات پر وہ حاوی ہوتے ہیں.پس خالی الہام بعض کمزور طبائع کے لئے امتیاز کا موجب نہیں ہوتے مگر الہام کے علاوہ انبیاء کو اپنے دعویٰ سے پہلے ایک پاکیزہ اور ممتاز زندگی مِلا کرتی ہے.قرآن کریم میں محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی نسبت اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ١ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ(یونس :۱۷) الہام میں غلطی دماغی کمزوری کا نتیجہ کہلا سکتی ہے لیکن اِس شان کے انسان کی طرف دماغی کمزوری کا منسوب کرنا مشکل ہو جاتا ہے پس گو الہام کی سچائی بھی ایک دلیل ہے.گو دعوے سے پہلے کی زندگی کی پاکیزگی بھی ایک دلیل ہے مگر یہ دونوں دلیلیں مِل کر ایک تیسری دلیل سچائی کی پیدا کر دیتی ہیں جو اپنی ذات میں بہت بڑی شان رکھتی ہے اور یہ فُرْقَان ہے.پھر قرآن کریم میں رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی سچائی کا ایک ثبوت یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اُن لوگوں کو تو دیکھو جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ خود اپنی ذات میں ایک بھاری ثبوت ہیں.آخر انسان مختلف درجات اور طبقوں کے ہوتے ہیں.کوئی بداخلاق اور طامع لوگ ہوتے ہیں.کوئی جاہل اور جلدی فریب میں آ جانے والے ہوتے ہیں مگر محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے بعض تو وہ تھے جنہوں نے خود اپنے ملک میں اپنے فن اور اپنی عقل اور اپنے علم کی وجہ سے خاص مرتبہ حاصل کیا ہوا تھا.ان لوگوں کا آپؐ پر ایمان لانا خود اپنی ذات میں آپؐ کی صداقت کی ایک بڑی بھاری دلیل تھی.وہ آدمی جو نہ جذباتی تھے نہ جاہل تھے نہ بد عمل تھے.دلیل اور عقل کے پیچھے چلنے والے ،علم رکھنے والے، قربانیاں کرنے والے، غرباء کی امداد کرنے والے اور مختلف فنون
Page 88
کے ماہر تھے آخر انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنی قوم میں اپنے آپ کو ذلیل کر کے ایک ایسے شخص کے پیچھے چلتے جو اپنے اندر سچائی کی علامتیں نہ رکھتا تھا.اسی طرح محمد رسول اﷲ صلی اللہ علیہ و آلہٖ وسلم کی سچائی کی دلیل خدا تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اُن کے دشمن تباہ ہو رہے ہیں.یہ بھی اپنی ذات میں ایک زبردست دلیل ہے مگر جس وقت یہ پچھلی تین دلیلوں سے مِل جائے تو یہ اور زیادہ شان پیدا کر دیتی ہےاسی طرح محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی سچائی کی ایک یہ بھی دلیل دی گئی ہے کہ موجودہ زمانہ میں جو مفاسد پیدا ہو رہے ہیں ان کو یہ دُور کرتا ہے.لوگوں کی علمی،اعتقادی اور عملی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے.یہ بات بھی اپنی ذات میں ایک بڑی بھاری دلیل ہے لیکن جس وقت یہ اُن دوسری دلیلوں کے ساتھ مل جاتی ہے تو یہ اور بھی زیادہ شان پیدا کر دیتی ہے.ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ بعض الہام طبعی بھی ہوتے ہیں اور خیالی بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہم مان لیتے ہیں کہ طبعی اور خیالی الہام بعض دفعہ سچے بھی ہو جاتے ہیں لیکن یہ ماننا ہمارے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ خیالی اور طبعی الہام جو دماغی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں اور شیطانی الہام جو دماغی اور اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہوتے ہیں انہوں نے اس شخص کو اپنے لئے منتخب کیا جس کی زندگی کی پاکیزگی کا سارا ملک شاہد تھا.چلو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ایسے طبعی یا خیالی یا شیطانی الہام ایک ایسے شخص کو ہو گئے جس کی پاکیزہ زندگی کا سارا ملک شاہد تھا لیکن ہمارے لئے یہ ماننا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک راستباز تھا اس کا دماغ بگڑ گیا لیکن باوجود اس کے ملک کے نہایت سمجھدار طبقہ کا ایک حصّہ جنہوں نے اسے قریب سے دیکھا تھا اور جن کی اپنی عقل کا ملک گواہ تھا اس کی سچائی پر گواہی دینے لگا پھر چلو ہم یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ غلطی بھی ہو گئی مگر یہ بات ہمارے لئے ماننی کتنی ناممکن ہو جاتی ہے کہ اس زمانہ کے غلط خیالات خواہ عقیدہ کے لحاظ سے ہوں یا علمی لحاظ سے ہوں یا عمل کے لحاظ سے ہوں ان کی اصلاح بھی اس شخص سے ہوئی.معترض مانتا ہے کہ شرک بُرا ہے اور معترض مانتا ہے کہ اس شرک کو محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے ہی دُور کیا.پھر وہ یہ بھی مانتا ہے کہ محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم الہام کے مدعی تھے اور اُس کے نزدیک اُن میں سے بعض اتفاقی طور پر پورے بھی ہو جاتے تھے.وہ مانتا ہے کہ محمدرسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی زندگی دعوے سے پہلے بڑی پاکیزہ تھی.وہ مانتا ہے کہ ان کے ماننے والے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کیا تھا اور وہ خود بھی اپنی عقل اور اپنے علم اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے مُلک میں مشہور تھے.وہ مانتا تھا کہ جنہوں نے محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو مانا وہ اتفاقی طور پر جیت گئے اور ان کے دشمن اتفاقی طور پر ہار گئے اور پھر وہ یہ بھی مانتا ہے کہ محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو شرک کے دُور کرنے کی بھی توفیق ملی.جس کی غلطی کو وہ خود بھی تسلیم کرنے والا ہے اسی طرح اور بیسیوں عقائد کی اصلاح کی توفیق
Page 89
آپ ؐ کو ملی جن میں سے بعض اصلاحات کے صحیح ہونے کو دشمنوں میں سے ایک فریق اور بعض کے صحیح ہونے کو دوسرا فریق مانتا ہے.اب اس سارے مجموعہ کو دیکھتے ہوئے کون شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نعوذباﷲ فاترالعقل تھے یا دماغ کی کمزوری کے مریض تھے یانعوذ باﷲشیطان سے تعلق رکھتے تھے.انبیاء میں کثرت سے ایسے دلائل کا جمع ہو جانا جو ان کی صداقت کو پوری طرح واضح کر دیں فرقان کہلاتا ہے ایک ایک دلیل میں الگ الگ تو شبہ پیدا کیا جاسکتا ہے.ایک ایک دلیل کو الگ الگ تو اتفاقی قرار دیا جا سکتا ہے مگر ان سب امور اور ایسے ہی اَور سینکڑوں امور کے ایک شخص کی ذات میں جمع ہو جانے کو توکسی صورت میں بھی اتفاق نہیں کہا جا سکتا.اگر اس اجتماع کے ہوتے ہوئے بھی شبہ باقی رہ سکتا ہے تو پھر دنیا کی کسی بات کو بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا.اسی مجموعے کا نام میرے نزدیک فُرْقَان ہے.یہی مجموعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا.یہی مجموعہ حضرت داؤد علیہ ا لسلام کو مِلا.یہی مجموعہ حضرت عیسٰی علیہ ا لسلام کو ملا.یہی مجموعہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو مِلا اور یہی مجموعہ آج بانیء سلسلہ احمدیہ سیّدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصّلوٰۃ و ا لسلام کو ملا ہے.انبیاء کو فرقان کا ملنا ان کے صادق ہونے کی زبردست دلیل ہے دشمن ہمیشہ ایک ایک چیز کو لے کر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اعتراض تو ہر چیز پر ہو سکتا ہے.دیکھنا یہ چاہیے کہ بیسیوں قسم کے دلائل کا مجموعہ اس میں کِس طرح جمع ہو گیا ہے.اگر ایسا مجموعہ کسی میں جمع ہو تو یقیناً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسے فُرْقَان ملا ہے اور یقیناً وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو گا.یہ فُرْقَان کبھی کسی جھوٹے آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتا.ہاں محمدرسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو دوسرے نبیوں سے ایک امتیاز حاصل ہے اور وہ یہ کہ دوسرے نبیوں کو کتاب اور اس کے علاوہ فُرْقَان ملا مگر محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو فرقان الگ بھی ملا.قرآن کریم کو فرقان کہے جانے کی وجہ اور محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اسے بھی فُرْقَان بنایا گیا.تورات اپنی سچائی کے لئے حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کے دوسرے معجزات کی تائید کی محتاج تھی.حضرت عیسیٰ علیہ ا لسلام کے الہامات دوسرے معجزات کی تصدیق کے محتاج تھے.وید اورژند کا بھی یہی حال ہے لیکن محمدرسول اﷲ صلی اﷲعلیہ و آلہٖ وسلم کی کتاب اپنی ذات میں بھی فُرْقَانہے یعنی وہ ایک زندہ کتاب ہے اور اگر دوسرے معجزات لوگوں کو بھول بھی جائیں تب بھی وہ اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اندر شامل رکھتی ہے اسی وجہ سے اس کا نام فُرْقَان رکھا گیا ہے اور کسی سابق الہامی کتاب کا نام فُرْقَان نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے دوسرے دلائل کی محتاج ہیں مگر قرآن کریم اپنی سچائی کا ثبوت اپنے اندر رکھتا ہے.اسی وجہ سے قرآنِ کریم
Page 90
کو ماننے والوں کی نسبت يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا (الانفال :۳۰) فرمایا گیا ہے یعنی یہ کتاب چونکہ خود فُرْقَان ہے اس لئے اس پر ایمان لانے والوں کو بھی اگر وہ درجۂ کمال تک ایمان لائیں فُرْقَان ملتا ہے.یہ دلیل انبیاء علیہم ا لسلام کی صداقت پہچاننے کی ایک ایسی زبردست اور جامع دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص اس دلیل کو سمجھ کر انبیاء کی شناخت کی کوشش کرے تو اس کے لئے اپنے زمانہ کے مامور کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں رہتا.لَعَلَّکُمْ تَھْتَدُوْنَ کی تشریح لَعَلَّکُمْ تَھْتَدُوْنَ فرماتا ہے یہ کتاب اور فرقان ہم نے موسیٰ کو اس لئے دئیے تھے تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پائیں مگر افسوس انہوں نے نہ کتاب سے فائدہ اُٹھایا اور نہ فرقان سے فائدہ اُٹھایا.لَعَلَّ کے لفظ سے اِس جگہ شک کا مفہوم نہیں سمجھنا چاہیے یہ شاہانہ کلام ہے اور گولغوی لحاظ سے اس لفظ میں قطعیت نہ پائی جاتی ہو لیکن شاہی کلام میں جب اس قسم کے الفاظ آئیں تو اُن میں قطعیت کا مفہوم ہی پایا جاتا ہے.بادشاہ اپنے فرامین میں ہمیشہ لکھتے ہیں کہ ہم فلاں قوم سے یہ امید کرتے ہیں حالانکہ اس سے مراد حکم ہوتا ہے.یہاں بھی لَعَلَّکُمْ تَھْتَدُوْنَکے یہی معنے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں دیں اور ہم بنی اسرائیل سے توقع رکھتے تھے کہ وہ ہدایت پائیں یعنی ہمارے احسان کا تقاضا تھا کہ وہ ہدایت پائیں اور اس کا طبعی نتیجہ یہی نکلنا چاہیے تھا کہ وہ ہدایت پا جاتے لیکن انہوں نے ہمارے احسان کی قدر نہ کی اور اپنی فطرت کو بھی ایسا مسخ کر دیا کہ طبعی نتیجہ یعنی ہدایت سے محروم ہو گئے.وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب موسیٰ ؑنے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم (کے لوگو) تم نے بچھڑے کو( معبود) بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِىِٕكُمْ فَاقْتُلُوْۤا بنا کر یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اس لئے تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکو اس طرح سے کہ اپنے (آدمیوں) کو اَنْفُسَكُمْ١ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِىِٕكُمْ١ؕ فَتَابَ (آپ) قتل کرو.یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہت اچھی ہے.تب اس نے عَلَيْكُمْ١ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ تمہاری طرف فضل کے ساتھ پھرتوجہ کی.وہ یقیناً (اپنے بندوں کی طرف )بہت توجہ کرنے والا (اور)
Page 91
الرَّحِيْمُ۰۰۵۵ بار بار رحم کرنے والا ہے.حَلّ لُغَات.ظَلَمْتُمْ.ظَلَمَ سے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے.اور ظَلَمَ کے لئے دیکھو حلّ لُغات سورہ ھٰذا ۵۲.اَنْفُسَکُمْ.اَنْفُسٌ نَفْسٌ کی جمع ہے اور اَلنَّفْسُ کے معنے ہیں(۱) اَلرُّوْحُ.رُوح (۲) اَلْجِسْمُ جسم.(۳) وَیُرَادُ بِالنَّفْسِ اَلشَّخْصُ وَالْاِنْسَانُ بِجُمْلَتِہٖ بعض اوقات نفس کا لفظ بول کر رُوح اور جسم کا مجموعہ انسان اور اس کا خاص تشخص مراد لیاجاتا ہے.(۴) اَلْعَظْمَۃُ.عظمت (۵) اَلْعِزَّۃُ.عزت (۶) اَلْھِمَّۃُ.ہمت (۷) اَ لْاِرَادَۃُ.ارادہ(۸)اَلرَّأَیُ.رائے.(اقرب) تُوْبُوْا.امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے.تَابَ اِلَیْہِ وَعَلَیْہِ کے معنے ہیں رَجَعَ عَلَیْہِ بِفَضْلِہٖ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا.(اقرب) بَارِئِکُمْ.اَلْبَارِیُٔ بَرَأَََ سے اسم فاعل ہے اور بَرَءَ اللہُ الْخَلْقَ کے معنے ہیں خَلَقَھُمْ اﷲ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اَلْبَارِیُٔ کے معنے ہیں اَلْخَالِقُ پیدا کرنے والا.(اقرب) اُقْتُلُوْا.اُقْتُلُوْا امر مخاطب جمع کا صیغہ ہے اور قَـتَلَہٗ کے معنے ہیں اَمَا تَہٗ بِضَرْبٍ اَوْحَجَرٍ اَوْسَمٍّ اَوْعِلَّۃٍ.کسی قسم کی ضرب یا پتھّرکے مارنے یا زہر دینے یا اور کسی وجہ سے اس کی رُوح کو اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا اور جب قَتَلَ الْجُوْعَ وَالْبَرْدَ کہیں تو معنے ہوں گے کَسَرَ شِدَّتَہٗ کہ اس نے بھوک کی تیزی اورسردی کی شدت کو دور کر دیا اور قَتَلَ اللہُ الْاِنْسَانَ وَقَاتَلَہٗ کے معنے ہیں لَعَنَہٗ.کہ اﷲ تعالیٰ نے فلاں شخص پر لعنت نازل کی اور اپنے سے دُور کر دیا.(اقرب) مفردات راغب میں اُقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْ کے ماتحت لکھا ہے لِیَقْتُلْ بَعْضُکُمْ بَعْضًا یعنی اس کے معنے یہ ہیں کہ تم میں سے غیر مشرک مشرک کو خود قتل کر دیں.وَقِیْلَ عُنِیَ بِقَتْلِ النَّفْسِ اِمَاطَۃُ الشَّھَوَاتِ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ قتلِ نفس سے مراد خواہشات نفسانیہ کو دُور کرنا ہے چنانچہ اسی معنے میں یہ محاور ہ بولا جاتا ہے کہ قَتَلْتُ الْخَمْرَبالْمَاءِ اَیْ اِذَا مَزَجْتُہٗ یعنی شراب کو پانی کے ساتھ ملا کر قتل کر دیایعنی اس کی شدّت کو ہلکا کر دیا نیز کہتے ہیں قَتَلْتُ فُـلَانًا وَ قَتَّلْتُہٗ اِذَا ذَلَّلْتُہٗ یعنی جب کسی کو عاجز اور ذلیل کر دیا جائے تو اس وقت بھی قتل کا لفظ استعمال
Page 92
کرتے ہیںاور کہہ دیتے ہیں کہ مَیں نے فلاں کو قتل کر دیا.لسان العرب میں قَتَلَ کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اﷲعلیہ و آلہٖ وسلم کے وصال پر جب خلافت کا انتخاب ہونے لگا تو بعض لوگوں نے اس وقت اختلاف کیا اور ان میں سے ایک سعد بھی تھے تو ان کے متعلق کہا گیا قَتَلَ اللہُ سَعْدًا فَاِنَّہٗ صَاحِبُ فِتْنَۃٍ وَ شَرٍّ کہ اﷲتعالیٰ سعد کو قتل کرے کیونکہ وہی فتنہ و فساد کی جڑ ہیں اور مطلب یہ تھا کہ دَفَعَ اللہُ شَرَّہٗ یعنی اﷲ تعالیٰ سعد کے شرّ کو دفع کرے اور اس کے ارادوں کو پورا نہ کرے.اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا.اُقْتُلُوْا سَعْدًا قَتَلَہُ اللہُ کہ سعد کو قتل کر دو اﷲ تعالیٰ اسے قتل کرے.اور مطلب یہ تھا کہ اِجْعَلُوْہُ کَمَنْ قُتِلَ وَ احْسِبُوْہُ فِیْ عِدَادِ مَنْ مَاتَ وَھَلَکَ وَلَا تَعْتَدُّوْا بِمَشْھَدِہٖ وَلَا تُعَرِّجُوْا عَلٰی قَوْلِہٖ یعنی اے لوگو تم سعد کی طرف التفات نہ کرو بلکہ اپنی توجہ کو اس سے ہٹا کر اسے ایسا کر دو کہ گویا وہ مقتول ہے اور اس کو ان لوگوں میں شمار کرو جو مر چکے ہوں اور اس کو کسی گنِتی میں نہ لاؤ اور اﷲ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی اس سے ایسا ہی سلوک کرے.اسی طرح حضرت عمرؓ سے ایک حدیث مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ مَنْ دُ عِیَ اِلٰی اِمَارَۃِ نَفْسہٖ اَوْغَیْرِہٖ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ فَاقْتُلُوْہُ اَیْ اِجْعَلُوْہُ کَمَنْ قُتِلَ وَمَاتَ بِاَنْ لَّا تَقْبِلُوْا لَہٗ قَوْلَہٗ وَلَا تُقِیْمُوْا لَہٗ دَعْوَۃً یعنی جو شخص اپنی خلافت یا اور کسی کی خلافت کا پروپیگنڈا کرے اور لوگوں کو کہے کہ اسے یا فلاں شخص کو خلیفہ بناؤ.اس کو قتل کردو یعنی اس کی بات کو قبول نہ کرو اور مکمل طور پر اس سے قطع تعلق کر لو اور اسے اس ذریعہ سے ایسا کر دو کہ گویا وہ مقتول ہے.اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے اِذَا بُوْیِعَ لِخَلِیْفَتَیْنِ فَاقْتُلُوا الْاَخِیْرَ مِنْھُمَا اَیْ اَبْطِلُوْا دَعْوَتَہٗ وَاجْعَلُوْہُ کَمَنْ مَاتَ کہ جب دو خلیفوں کی بیعت کی جاوے تو آخری کو قتل کر دو یعنی اس کی دعوت کی طرف کان نہ رکھو بلکہ اس سے قطع تعلق کر کے اسے قتل کئے جانے کے حکم میں کر دو.(لسان) پس قَتَلَ کے عام مشہور معنوں کے علاوہ اس کے معنے ذلیل کرنے اور قطع تعلق کرنے کے بھی ہیں.اَنْفُسَکُمْ.اَنْفُسَکُمْ کے لئے دیکھو حَلِّ لُغَات آیت۴۵ سورئہ ھٰذا.تَابَ.تَابَ اِلَیْہِ وَعَلَیْہِ کے معنے ہیں رَجَعَ عَلَیْہِ بِفَضْلِہٖ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا.(اقرب) اَلتَّوَّابُ.تَوَّابٌ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنے ہیں فضل کے ساتھ بہت متوجہ ہونے والا.اَلرَّحِیْمُ.اَلرَّحِیْمُبھی رَحِـمَ سے نکلا ہے اور فَعِیْلٌ کے وزن پر ہے جس کے معنوں میں تکرار اور استحقاق کے مطابق سلوک کا مفہوم پایا جاتا ہے.(تفسیر البحر المحیط زیر تفسیر سورۃ الفاتحۃ ) پس
Page 93
اس کے معنی ہوئے جو رحم کے حقدار کو اس کے کام کی اچھی جزاء دیتا ہے اور بار بار اس پر رحم نازل کرتا جاتا ہے.علم صرف کے زبردست امام ابو علی فارسی کہتے ہیں.اَلرَّحْمٰنُ اِسْمٌ عَامٌ فِیْ جَمِیْعِ اَنْوَاعِ الرَّحْمَۃِ یَخْتَصُّ بِہِ اللّٰہُ تَعَالٰی وَالرَّحِیْمُ اِنَّمَا ھُوَ فِیْ جِہَۃِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ قَالَ تَعَالٰی کَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْـمًا (تفسیرفتح البیان زیر تفسیر سورۃ الفاتحۃ ) یعنی اَلرَّحْمٰن اسم عام ہے اورہر قسم کی رحمتوں پر مشتمل ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے اور اَلرَّحِیْم مومنوں کی ذات سے تعلّق رکھتا ہے یعنی اَلرَّحِیْم کی رحمت نیکو کاروں سے مخصوص ہے.چنانچہ اس کا ثبوت قرآن کریم کی آیت وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ہے.(الاحز اب :۴۴) ابن مسعودؓ اور ابو سعید خدریؓ کی روایت ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَلرَّحْمٰنُ رَحْمٰنُ الدُّنْیَا.وَالرَّحِیْمُ.رَحِیْمُ الْاٰخِرَۃِ (تفسیر البحر المحیط زیرتفسیر سورۃ الفاتحۃ ) رسول کریم صلعم نے فرمایا کہ رحمٰن دُنیا کی رحمتوں پر نظر رکھتے ہوئے ہے اور الرَّحِیْم کا نام آخرت کی رحمتوں پر نظر کرتے ہوئے ہے.اس سے بھی معلوم ہوا کہ رحمٰن کے معنے بلا مبادلہ اور بغیر استحقاق رحم کے ہیں کیونکہ اس قسم کا رحم زیادہ تر اس دُنیا میں جاری ہے اور رحیم کے معنی نیک کاموں کے اعلیٰ بدلہ کے ہیں کیونکہ آخرت مقامِ جزا ہے.تفسیر.یہ بتانے کے بعد کہ بنی اسرائیل نے اس موقع پر بھی جبکہ عظیم ترین احسان ان پر ہو رہا تھا خدا تعالیٰ کی شدید ترین نافرمانی کی.فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ائمۃالکفر کو اس موقع کے لحاظ سے سزا دینی ضروری تھی کیونکہ ایسے عظیم الشان موقع پر شرک کا جُرم کلّی طور پر معاف کر دینا گناہوں پر دلیر کرنے کا موجب ہو سکتا تھا.پس فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم نے اپنی جان پر شرک کر کے بڑا ظلم کیا ہے اس لئے اپنے بَارِیٔ کے حضور بہت توبہ کرو.بَارِیٔ کے معنے جیسا کہ حَلِّ لُغَات میں بتائے گئے ہیں پیدا کرنیوالے کے ہیں.لیکن خَالِقٌ کے لفظ سے اس کے معنو ں میں کچھ فرق ہے بَرَئَ کا لفظ عیب اور نقص سے پاک ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے اس لئے ائمہ زبان نے اس کے معنے نقائص سے پاک خلق کے کئے ہیں چنانچہ زمخشری اپنی کتاب کشّاف میں لکھتے ہیں اَلْبَارِیُٔ ھُوَالَّذِیْ خَلَقَ الْخَلْقَ بَرِیْئًا مِّنَ التَّفَاوُتِ یعنی بَارِیٌٔ کے معنے ہیں وہ جس نے مخلوق کو اختلاف و نقصان سے پاک پیدا کیا ہو.علاّمہ ابوحیّان نے بھی ان کے ان معنوں کی تعریف کی ہے اور علّامہ ابوحیّان علم نحو اور لغت کے ایک بہت بڑے ماہر ہیں اور ان کی تفسیر بحرالمحیط چوٹی کی تفسیروں میں سے ہے وہ زمخشری کے اس استدلال کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ یہ استدلال کلام حسن ہے یعنی بہت لطیف استدلال ہے.یہ استدلال علّامہ زمخشری کا
Page 94
اس لفظ کے دوسرے الفاظ سے ہے.بَرْءٌ کے معنے عربی زبان میں عیب و نقص سے پاک ہونے کے ہوتے ہیں.لفظ بَرَءٌ اور خَلْقٌ میں فرق لسان العرب میں بھی لکھا ہے کہ خَلْقٌ اور بَرْءٌ میں یہ فرق ہے کہ خلق سب قسم کی مخلوق کے لئے آتا ہے لیکن بَرْءٌ کا لفظ عموماًذوی الارواح کی نسبت بولا جاتا ہے چنانچہ عرب کہتے ہیں بَرَءَ اللہُ النَّسِمَۃَ وَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ یعنی ارواح کی پیدائش کے لئے بَرَءَ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش کے لئے خَلَقَ کا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ نسبتاً کامل مخلوق کی پیدائش کے لئے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے.قرآن کریم میں مصائب کی پیدائش کی نسبت بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے (الحدید: ۲۳ ) مگر وہاں بھی چونکہ ذوی الارواح کا ہی ذکر ہے یہ استعمال مشارکت کی وجہ سے ہوا ہے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ بَارِیٌٔ کا عام استعمال غیر ذی الارواح کے لئے جائز ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ(الحشر:۲۵) یعنی اﷲ باریٔ اور خالق ہے ایک جگہ دونوں لفظوں کا استعمال بتاتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک دونوں لفظ ہم معنٰی نہیں ہیں بلکہ دونوں الگ الگ خصوصیت کے حامل ہیں.پس اﷲ تعالیٰ کے بَارِیٌٔ نام کے یہ معنی ہیں کہ نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ وہ خاص قسم کے اخلاق اور ترقی کرنے والی قوتیں بھی عطا فرماتا ہے پس اس جگہ پر بَارِیٌٔ کا لفظ استعمال فرما کر ایک لطیف اشارہ شرک کی تردید کے متعلق کیا ہے اور وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے بھی گھڑ گھڑا کر ایک بُت تیار کیا تھا.ظاہر ہے کہ خالق مخلوق سے اچھا ہوتا ہے اور گھڑنے والا گھڑی ہوئی چیز سے بہتر ہوتا ہے.ایک تصویر بڑی اچھی چیز ہے مگر اس کا مصوّر اس سے بھی زیادہ قابلِ قدر ہے کیونکہ وہ ویسی ہی بلکہ اس سے بڑھ کر تصویریں بنانے کی قابلیت رکھتا ہے.تُوْبُوْا اِلٰی بَارِئِکُمْ کہہ کر فرمایا کہ اے نادانو! تم اپنے ہاتھ کی ادنیٰ اور بے جان گھڑی ہوئی چیزوں کے آگے سجدہ کرنے لگ گئے.لیکن جس نے تم کو کامل طور پر جاندار بنا کر پیدا کیا تھا اس کو بھُول گئے.اگر صنعت کوئی قابلِ قدر چیز ہے تو صنّا ع اس سے بھی بڑھ کر قابلِ قدر ہے کیونکہ وہ صنعتوں کا منبع ہے.پس اگر کوئی اچھی صنعت تمہاری توجہ کو کھینچ لیتی ہے تو تمہیں صنعت سے صانع کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی اور شرک کی بجائے توحید کو اختیار کرنا چاہیے تھا.غرض تُوْبُوْۤا اِلٰى بَارِىِٕكُمْ کہہ کر توبہ کے مضمون کے علاوہ صرف اﷲ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے کی ضرورت اور حقیقت پر ایسی روشنی ڈالی ہے کہ تین لفظوں میں ہزروں الفاظ کا مضمون بیان کر دیا گیا ہے.اُقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْ میں قتل کے معنے حقیقۃً قتل کرنے کے بھی ہوتے ہیں فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ.قتل کے معنی جیسا کہ حلِّ لغات سے ظاہر ہے قتل کے بھی ہوتے ہیں اور قطع تعلق کے بھی ہوتے ہیں.بعض مفسّرین نے اس جگہ پر قتل سے مراد اپنے نفس کو قتل کرنے یعنی اپنی خواہشات کو مارنے کے لئے ہیں لیکن بائبل سے ظاہر ہوتا
Page 95
ہے کہ فی الواقع بعض آدمیوں کو قتل کی سزا دی گئی تھی اور اِس بات کو دیکھتے ہوئے کہ پہلے عفو کا اعلان کرنے کے بعد پھر اﷲ تعالیٰ نے اس موقع کی شناخت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت بعض افراد کو قتل کی سزا بھی دی گئی تھی.بائبل میں بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کے قتل کئے جانے کا واقعہ بائبل میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے.’’ اور اُس (موسیٰ)نے اُنہیں (بنولاوی کو) کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر مرد اپنی کمر پر تلوار باندھے اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک تمام لشکر گاہ میں گزرتے پھر و اور ہر مرد تم میں سے اپنے بھائی کو.ہر ایک آدمی اپنے دوست کو اور ہر ایک آدمی اپنے قریب کو قتل کرے اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہے کے موافق کیا چنانچہ اُس دن لوگوں میں سے قریب تین ہزار مرد مارے پڑے.‘‘ (خروج باب ۳۲.آیت ۲۷.۲۸) پھر آگے لکھا ہے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام نے جا کر رحم کی درخواست کی اور کہا.’’ کاش کہ تو اُن کا گناہ معاف کرتا اگر نہیں تو میں تیری منّت کرتا ہوں کہ مجھے اپنے اُس دفتر سے جو تو نے لکھا ہے میٹ دے.‘‘ (خروج باب ۳۲آیت ۳۲) اس پر خدا تعالیٰ نے بحیثیت قوم تو گناہ معاف کر دیا لیکن مِن حیث الافراد معاف نہ کیا اور کہا کہ قیامت کو پُرسش ہو گی.(خروج باب ۳۲آیت ۳۴) بنی اسرائیل کو بچھڑا بنانے کے بعد قومی معافی اور فردی سزا دیئے جانے میں بائبل اور قرآن مجید کا اختلاف اور اصل حقیقت بائبل کے ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ پہلے ان کو قتل کی سزا دی گئی.اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر رحم کیا گیا اور قومی طور پر سزا اُٹھا دی گئی.لیکن قیامت کے دن کی پرسش کو قائم رکھا گیا.قرآن کریم اور بائبل کے اِس بیان میں کچھ اختلاف ہے.قرآن کریم کے بیان کے رو سے قومی معافی پہلے ہوئی اور فردی سزا بعد میں دی گئی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق فردی سزا پہلے دی گئی اور پھر قوم کومعافی ملی.جہاں تک الہامی شہادت کا سوال ہے لازماً یہودیوں اور عیسائیوں کو بائبل کے بیان پر اعتبار ہو گا اور ایک مسلمان کو قرآن کریم کے بیان پر اور جہاں تک تاریخ کا سوال ہے سوائے بائبل اور قرآن کریم کے بیان کے اور کوئی شہادت اس بارہ میں ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جن دوسرے مقامات پر بائبل اور قرآن کریم میں اختلاف
Page 96
ہوا ہے اور جن کی نسبت آزاد تاریخی شہادت بھی موجود ہے ایسے مواقع پر نتیجہ ہمیشہ یہی نکلا ہے کہ قرآن کریم کی بات سچی اور بائبل کی بات غلط ثابت ہوئی ہے پس تاریخی لحاظ سے بھی قرآن کریم کے بیان کو بائبل کے بیان پر مقدّم کرنا پڑے گا لیکن یہ واقعہ ایک حد تک نفسیاتی اصول سے بھی تعلق رکھتا ہے.ظاہر ہے کہ جب ایک قوم جُرم کرے تو سارے ہی جُرم کرنے والوں کے خلاف یک دم قدم اُٹھایا جاتا ہے پھر اگر معاف کرنا ہو تو عام قوم کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جو زیادہ مجرم ہوں ان کو سزا دے دی جاتی ہے پس اس نفسیاتی اصول کے لحاظ سے بھی قرآن کریم کی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے.جب حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام نے خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کیا.اور قوم میں ندامت پیدا ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی تو اﷲتعالیٰ نے اُن کی تسلّی کے لئے ان پر ظاہر کر دیا کہ اُن کی قوم من حیث القوم تباہ نہیں کی جائے گی.اس اعلان کے بعد جو اَ ئمۃ الکفر تھے اُن کے لئے سزا تجویز کر دی گئی لیکن بائبل کے بیان کے مطابق پہلے اﷲ تعالیٰ نے سب کے قتل کا حکم دیا.پھر حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کی فریاد پر جو پہلے دن مارے گئے تھے اُن کے سوا باقیوں کو چھوڑ دیا.یہ ترتیب نہ صرف غیر طبعی ہے بلکہ ظالمانہ بھی ہے کیونکہ قرآنی بیان کے مطابق تو عام طور پر قوم کو معاف کر دیا گیا تھا اور اَ ئمۃا لکفر کو سزا دی گئی تھی.لیکن بائبل کے بیان کے مطابق پہلے دن ایک دوسرے کو بنی اسرائیل نے مارا.اتفاقاً جو پہلے دن مر گئے وہ مر گئے اور جو بعد میں بچ گئے چاہے وہ اَ ئمۃ الکفر تھے یا عوام.اُن کو معاف کر دیا.گویا سزا میں جُرم کی اہمیت کو بالکل مدنظر نہیں رکھا گیا صرف وقت کو مدنظر رکھا گیا کہ جو پہلے مارے گئے سو مارے گئے اور جو بعد میں بچ گئے سوبچ گئے.حالانکہ جو سزا شرعی قانون کے مطابق دی جاتی ہے اس میں اہمیتِ جرم کو ضرور مد نظر رکھا جاتا ہے ہاں قانونِ طبعیّت کے اصول اور ہیں.پس قرآن کریم کا بیان ہی انصاف اور عدل کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوںنے نادانی اور رُعب کے ماتحت کام کیا تھا ان کو تو معاف کر دیا اور جو بڑے بڑے مجرم تھے ان کو سزائیں دے دیں.َاُقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ میں اَنْفُسَکُمْ سے مراد بنی اسرائیل کے مخصوص افراد یا سردار ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ فَاقْتُلُوْۤا اَنْفُسَكُمْ سے مراد یہ نہیں کہ اپنے آپ کو مار دو بلکہ مراد قوم کے مخصوص افراد یا سردار ہیں.قرآن کریم میں اِسی سورۃ کی آیت نمبر۸۵ میں آتا ہے.وَ لَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ (البقرة :۸۵) اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو حالانکہ مراد اپنی قوم کے لوگ ہیں کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالا نہیں کرتا.اسی طرح سورۃ توبہ آیت ۳۶ میں آتا ہے.فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ(التوبۃ :۳۶) یعنی حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو.اور مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو.اسی طرح سورۂ نور میں آتا ہے.فَاِذَا
Page 97
دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةً (النّور:۶۲) جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنی جانوں کو سلام کہو اور مراد یہ ہے کہ تمہارے وہ بھائی جو اِن مکانوں میں رہتے ہیں ان کو سلام کہو.پس فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْکے معنٰی یہ ہیں کہ اپنے اعزّاء و اقرباء کو قتل کرو جیسا کہ بائبل میں بھی مذکور ہے.بچھڑے کی پرستش کی تحریک کے لیڈروں کو ان کے رشتہ داروں سے قتل کروانے کی حکمت معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کے سردار ثابت ہوئے تھے اُن کے متعلق یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے بھائی یا دوست ہی اُن کو قتل کریں.اس میں دو فائدے مدِّنظر تھے.ایک تو یہ کہ جو قتل ہوا اس کو تو قتل کی سزا مِل گئی اور جس نے قتل کیا اس کو بھی ایک رنگ میں سزا مل گئی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی یا دوست کو مارنا پڑا اور اس کی موت کا نظارہ دیکھنا پڑا.دوسرا فائدہ اس میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی بُنیاد قبائل پر تھی اور جن قوموں کی بُنیاد قبائلی زندگی پر ہوتی ہے اُن میں رقابت بہت شدید ہوتی ہے اگر قتل کرنے والے غیر ہوتے تو بنی اسرائیل کے قبائل میں شدید دشمنی پیدا ہو جاتی اور وہ مقتول کی شرارت کو بھول جاتے اور یہی بات اُن کے دل پر غالب رہتی کہ ان کے ایک بھائی یا دوست کو فلاں غیر شخص نے قتل کر دیا تھا اور اُس کا کینہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے پس اﷲ تعالیٰ نے مزید فتنہ سے بچانے کے لئے اُن کو یہ حکم دیا کہ قریبی اپنے قریبی کو اور دوست اپنے دوست کو خود مارے تاکہ ایک طرف تو اُس کے دل کو دُکھ پُہنچ کر اس کی رُوحانی اصلاح ہو اور دوسری طرف اُس کا دل اپنے بھائیوں کے کینہ سے محفوظ رہے.یہاں تو اﷲ تعالیٰ نے اس حکمت کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور شائد انہوں نے کرھًاہی اس پر عمل کیا ہو گا.آنحضرت صلعم کے صحابہ اور حضرت موسیٰ کے متبعین میں فرق لیکن رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے طوعاً اپنے آپ کو اس خدمت کے لئے پیش کیا جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی صحبت میں رہنے والے لوگ اخلاق کے نہایت ہی اعلیٰ معیار پر پہنچ چکے تھے.جنگ بنوالمصطلق کے موقع پر جب رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پر ایک ہی کنواں تھا اور پانی نکالنے والے زیادہ تھے.جلدی کی وجہ سے بعض لوگوں میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا.اتفاق کی بات ہے یہ اختلاف ایک طرف انصار میں اور دوسری طرف مہاجرین میں ہوا اور بغیر کسی ارادے کے دو پارٹیاں سی بن گئیں.ایک طرف مہاجرین کا گروہ نظر آنے لگا اور ایک طرف انصار کا.منافقوں کے سردار عبداﷲ بن اُبَی ابن سلول نے جب یہ حالت دیکھی تو اس سے فائدہ اُٹھانے کا ارادہ کیا اور انصار کو مخاطب کر کے بڑے زور سے کہا تم نے خود ہی ان لوگوں کو سر پر چڑھا لیا ہے ورنہ اِن کی حیثیت کیا تھی کہ ہمیں ذلیل کرتے.اب ذرا مدینے واپس پہنچ لینے دو لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ
Page 98
مِنْهَا الْاَذَلَّ (المنافقون:۹) مدینے کا سب سے بڑا معزز آدمی یعنی عبداﷲ بن اُبَی ابن سلول مدینہ کے سب سے ذلیل آدمی یعنی نعوذ باﷲمن ذالک محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو وہاں سے نکال دے گا.یہی وہ معنے تھے جو صحابہؓ نے لئے.ہو سکتا ہےکہ اس کی مراد یہ ہو کہ معزز قوم یعنی انصار ذلیل قوم یعنی مہاجرین کو نکال دے گی.مگر بات پھر بھی وہی آجاتی ہے.صحابہ ؓ میںگو اس وقت اختلاف اور جوش پیدا تھا مگر عبداﷲ بن اُبیَ ابن سلول کے منہ سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ اُن کے ہوش ٹھکانے آگئے.انصار نے فوراً سمجھ لیا کہ ہمارے ایمان کی آزمائش کا وقت ہے انہوں نے جھگڑا وہیں ختم کر دیا اور مہاجرین کے لئے جگہ چھوڑ دی.مہاجرین نے تو اس وجہ سے کوئی جوش نہ دکھایا کہ خود اُن کے ساتھ جھگڑا تھا مگر انصار میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں کہ اِس فقرہ کے کہنے کے بعد عبداﷲ بن اُبَی ابن سلول زندہ رہنے کے قابل نہیں.عبدا ﷲ بن اُبَی ابن سلول کے بیٹے کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے بھی اپنے دل میں یہی فیصلہ کیا کہ میرا باپ اب زندہ رہنے کے قابل نہیں.اور وہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اﷲ آپؐ کو وہ بات پہنچی ہے جو میرے باپ نے کہا ہے.آپؐ نے فرمایا ہاں پہنچی ہے اس کے بعد اُس نے کہا یا رسول اﷲ میرے باپ کے اس جرم کی سزا سوائے قتل کے اَور کیا ہو سکتی ہے مگر مَیں ایک عرض کرتا ہوں کہ جب آپؐ میرے باپ کے قتل کا حکم دیں تو میرے ہاتھ سے اُ س کو قتل کروائیں کیونکہ یا رسول اﷲ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی اَور شخص کے ہاتھ سے وہ قتل ہو اور میرا نفس کسی وقت مجھے یہ جوش دلائے کہ وہ سامنے میرے باپ کا قاتل جاتا ہے اُس سے بدلہ لے.مَیں چاہتا ہوں کہ میرا باپ میرے ہی ہاتھ سے قتل ہو جائے تاکہ کسی مسلمان کا بُغض میرے دل میں پیدا نہ ہو ( السیرۃالنبویۃ لابن ہشام غزوۃ بنی المصطلق.طلب ابن عبداللہ بن اُبَی ان یتولّی ھو قتل ابیہ) دیکھو صحابہ ؓ کی نظر کیسی باریک بین تھی.عبداﷲ بن اُبَی ابن سلول کا بیٹا اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے اس لئے قتل نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی ہتک کی ہے.وہ جانتا ہے کہ جُرم خواہ کتنا ہی بڑا ہو بہر حال وہ اس کا باپ ہے.پس وہ اس جوش کی وجہ سے اسے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کرنا چاہتا کہ اُس نے رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی کیوں ہتک کی.وہ اُسے اس وجہ سے اپنے ہاتھ سے قتل کرنا چاہتا ہے تاکہ کسی اور مسلمان بھائی کا بُغض اس کے دل میں پیدا نہ ہو.گویا بنی اسرائیل کو جس حکمت کی طرف وحی جلی سے خدا تعالیٰ کو توجہ دلانی پڑی محمدرسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے صحابہؓ آپ ہی آپ اپنے نورِ ایمان کی وجہ سے وَحْیِ جَلِیْ کے بغیر وَحْیِ خَفِیْ کی مدد سے اس نکتہ تک جا پہنچے.رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوْاعَنْہُ.ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِىِٕكُمْاس میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو مَیں اوپر بیان کر چکا ہوں.
Page 99
یعنی اَئمۃ الکفر کو سزا ملنا تمہاری قوم کے لئے بہتر ہے کیونکہ تمہاری قوم کی قلبی حالت ایسی ہے کہ عفو اس کی اصلاح نہیں کر سکتا.کسی قدر سزا اس کے ساتھ شامِل ہونی چاہیے اور دوسرے اِس طرف بھی اشارہ ہے کہ بھائیوں سے بھائیوں اور دوستوں سے دوستوں کو مروانے میں تمہارے لئے بہتری ہے ورنہ تمہاری قوم اتنی مغلوب الغضب ہے کہ اگر غیروں کے ہاتھ سے انہیں قتل کروایا گیا تو تمہارے اندر انتقام کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا.فَتَابَ عَلَيْكُمْ پھر خدا تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل نازل کیا اور رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوا.یعنی اﷲ تعالیٰ نے تمہارے اس جرم کو ان سزاؤں کے بعد بھلا دیا اور اگر تم مزید جرائم نہ کرتے تو خدا تعالیٰ تمہارے اس جرم کو کبھی یاد نہ دلاتا.اِنَّہٗ ھُوَالتَّوَّابُ الرَّحِیْمُکی تشریح اِنَّہٗ ھُوَالتَّوَّابُ الرَّحِیْمُ وہ یقیناً بہت ہی فضل اور رحمت نازل کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے یعنی بعد کے واقعات خود تمہارے پیدا کردہ ہیں ورنہ اتنے عظیم الشّان احسان کے موقع پر بنی اسرائیل کا اتنا خطرناک جُرم اُس نے پوری طرح معاف کر دیا تھا لیکن افسوس کہ انہوں نے جیسا کہ آئندہ واقعات ظاہر کریںگے خدا تعالیٰ کی اس عظیم الشان بخشش کی قدر نہ کی.بائبل کا بچھڑے کی پرستش کے نتیجہ میں مقتولین کی تعداد کو تین ہزار قرار دینا مبالغہ ہے جیسا کہ اوپر نوٹ میں خروج کے حوالہ سے بتایا جا چکا ہے بائبل کے بیان کے مطابق تین ہزار آدمی تھے جو اُس دن مارے گئے مگر یہ بات عقل کے بالکل خلاف ہے.اگر صرف اَئِـمّۃُ الْکُفر ہی اُن میں تین ہزار تھے تو قوم تو لاکھوں کی چاہیئے تھی لیکن اُس وقت کے بنی اسرائیل کا لاکھوں کی تعداد میں ہونا نہ تو تاریخ سے ثابت ہوتا ہے اور نہ واقعات اس کی اجازت دیتے ہیں.آج اتنے سامانوں کی موجودگی میں دشتِ سینا میں سے لاکھوں کی قوم آسانی سے نہیں گزر سکتی تو اُس زمانہ میں جبکہ کوئی سامان موجود نہیں تھے یہ لاکھوں کی جمعیت جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے کس طرح گزر سکی تھی.جہاں تک قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور جہاں تک عقل شہادت دیتی ہے یہ ہجرت کرنے والے بنی اسرائیل صرف چند ہزار افراد تھے ممکن ہے تین قبائل میں سے چند آدمی مارے گئے ہوں اور بائبل کے مبالغہ نویسوں نے اُن کو تین ہزار بنا دیا ہو.
Page 100
وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تیری بات ہر گز نہیں مانیںگے جب تک ہم اللہ کوآمنے جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ۰۰۵۶ سامنے نہ دیکھ لیں اس پر تمہیں ایک مہلک عذاب نے پکڑ لیا اور تم( اپنی آنکھوں سے اپنے فعل کا انجام) دیکھ رہے تھے.حَلّ لُغَات.جَھْرَۃً.اَلْجَھْرَۃُ کے معنے ہیں مَاظَھَرَ جو چیزسامنے نظر آ رہی ہو اور آیت لَنْ نُّـؤْمِنَ.....الخ میں جَھْرَۃًکے معنی ہیں عَیَانًا غَیْرَ مُسْتَتِرٍ یعنی کھلم کھلا.ظاہر.(اقرب) اَلصَّاعِقَۃُ.اَلصَّاعِقَۃُ کے معنے ہیں اَ لْمَوْتُ.موت.کُلُّ عَذَابٍ مُھْلِکٍ.ہر مہلک عذاب.صَیْحَۃُ الْعَذَابِ.عذاب کی آواز.نَارٌ تَسْقُطُ مِنَ السَّمَآئِ فِیْ رَعْدٍ شَدِیْدٍ لَا تَمُرُّ عَلٰی شَیْ ءٍ اِلَّا اَحْرَقَتْہُ وہ آگ جو بادل سے کڑک کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور جس چیز پر گرے اُسے جلا دیتی ہے (یعنی گرنے والی بجلی) (اقرب) اَلصَّاعِقَۃُ.ھِیَ الصَّوْتُ الشَّدِیْدُ مِنَ الْجَوِّ ثُمَّ یَکُوْنُ مِنْہُ نَارٌ فَقَطْ اَوْ عَذَابٌ اَوْ مَوْتٌ وَھِیَ فِیْ ذَاتِھَا شَیْ ءٌ وَّاحِدٌ وَھٰذِہِ الْاَشْیَآ ءُ تَأْثِیْرَاتٌ مِّنْھَا.صَاعِقَہ اس ہولناک گرج اور آواز کو کہتے ہیں جو فضا سے پیدا ہوتی ہے پھر اس سے کبھی تو آگ واقع ہوتی ہے یا عذاب یا موت نازل ہوتی ہے.تفسیر.یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ بعض ضدّی لوگ جب دلائل اور براہین کا جواب نہیں دے سکتے تو ایسی شرائط لگانے لگتے ہیں جو بے فائدہ ہوں اور جن سے سوائے بات ٹالنے کے اور کچھ مقصود نہ ہو.اس زمانہ میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جب ہستی باری تعالیٰ کو دلائل سے ثابت شدہ دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو تب تک نہ مانیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں.بنی اسرائیل میں سے بھی معلوم ہوتا ہے ایک جماعت نے حضرت موسیٰ ؑسے ایسا مطالبہ کیا گو بائیبل میں اس کا ذکر نہیں لیکن یہ ایک ایسا عام سوال ہے جو قریباً ہر زمانہ میں صداقت کے مقابلہ میں ہوتا آرہا ہے اور اس بات کی صداقت میں قرآن کریم کے مخالف بھی شک نہیں کر سکتے چونکہ قرآن کریم خود الٰہی کلام ہونے کا مدعی ہے اس لئے ضروری نہیں کہ بائبل کے بیان کردہ امور سے زائد کسی واقعہ کا ذکر نہ کرے.اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے متعلق ایک ہی قسم کے دو سوال اور ان میں فرق اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اس مطالبہ پر کہ ہمیں خدا تعالیٰ دکھا دو عذاب نازل ہوا مگر حضرت موسیٰ ؑنے بھی تو رَبِّ اَرِنِیْ
Page 101
اَنْظُرْ اِلَیْکَ کہا تھا (الاعراف:۱۴۴ ) یعنی اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا تا مَیں بھی تجھے دیکھوں لیکن اُن پر غضب نازل نہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ؑ نے تو محبت کے تقاضے سے سوال کیا اور ان لوگوں نے یہ شرط لگا دی کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں اور یہ گستاخی اور شرارت ہے اس لئے خفگی کا الہام ہوا.اگر حق کو قبول کر کے رؤیت کا سوال کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طر ح ان پر بھی ناراضگی کا اظہار نہ کیاجاتا.اَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ میں صاعقہ سے مراد فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ.صَاعِقَہ کے معنے عربی زبان میں عذاب کے ہیں.لسان العرب میں لکھا ہے قِیْلَ اَلصَّاعِقَۃُ.اَلْعَذَابُ یعنی اہلِ لغت کہتے ہیں کہ صاعقہ عذاب کو کہتے ہیں.اس لفظ کی باریک تحقیقات سے معلوم ہوتا کہ اس کا اطلاق خصوصاً ایسے عذابوں پر ہوتا ہے جن کے ساتھ سخت آواز ہو جیسے زلزلہ، بجلی یا بادِتُند کا عذاب.کبھی صاعقہ کے معنے موت یا غشی کے بھی ہوتے ہیں لیکن اصل معنے وہی ہیں جو اوپر لکھے گئے اور موت اور غشی کے معنے صرف اس لئے رواج پا گئے کہ اکثر خطرناک عذابوں کا نتیجہ موت یا غشی ہوتا ہے.قرآن کریم میں صاعقہ کا لفظ زیادہ تر عذاب کے ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ فرمایا ہے.فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ( حٰمٓ سجدہ :۱۴) یعنی اگر یہ لوگ تیری باتوں سے اعراض کریں تو تُو اُن کو کہہ دے کہ میں تمہیں ایسے صاعقہ سے ڈراتا ہوں جو عاد و ثمود کے صاعقہ کی طرح ہو گا اور آگے چل کر عاد کے صاعقہ کی یہ تشریح کی ہے کہ انہیں ایک بادِتُند کے عذاب کے ساتھ سزا دی گئی تھی.اسی طرح ثمود کے صاعقہ کی تشریح سورۂ اعراف آیت ۷۹ میں یوں بیان فرمائی ہے.فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کہ ثمود کی قوم ایک سخت زلزلہ سے تباہ کی گئی تھی.پس معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں صاعقہ بمعنے عذاب استعمال ہوتا ہے اور آیت زیرِ تفسیر میں بھی اس سے عذاب ہی مراد ہے.ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ۰۰۵۷ پھر ہم نے تمہاری ہلاکت کے بعد تمہیں اس لئے اٹھایا کہ تم شکر گزار بنو.حَلّ لُغَات.بَعَثْنَا.بَعَثَ سے متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے اور بَعَثَہٗ (یَبْعَثُ) بَعْثًا کے معنے ہیں.اَرْسَلَہٗ اس کو بھیجا نیز کہتے ہیں بَعَثَہٗ بَعْثًا اور مطلب یہ ہوتا ہے اَثَارَہٗ وھَیَّجَہٗ اس کو برانگیختہ کیا اور جوش دلایا اور
Page 102
جب بَعَثَہٗ عَلَی الشَّیْ ءِ کہیں تو اس کے معنی ہوں گے حَمَلَہٗ عَلٰی فِعْلِہٖ اس کو کسی کام کے کرنے پر آمادہ کیا جب بَعَثَ کے فعل کو اﷲ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں اور کہیں کہ بَعَثَ اللہُ الْمَوْتٰی تو اس کے معنے ہوں گے اَحْیَاھُمْ اﷲ تعالیٰ نے مرُدوں کو زندہ کیا اور اَلْبَعْثُ کے معنے ہیں اَلنَّشْرُ اُٹھانا (اقرب) پس بَعَثْنٰـکُمْ کے معنے ہوں گے ہم نے تم کو اُٹھایا.مَوْتِکُمْ.اَ لْمَوْتُ.زَوَالُ الْحَیَاۃِ عَنْ مَّنْ اِتَّصَفَ بِھَا.اس چیز سے زندگی کا علیحدہ ہو جانا جو زندگی کے ساتھ متصف ہو (اقرب)مفردات میں ہے.اَلْمَوْتُ زَوَالُ الْقُوَّۃِ الْـحَیَوَانِیَّۃِ وَاِبَانَۃُ الرُّوْحِ عَنِ الْجِسْمِ.قوت حیوانیہ اور رُوح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا موت کہلاتا ہے.اَنْوَاعُ الْمَوْتِ بِحَسْبِ الْحَیٰوۃِ.موت کئی قسم کی ہوتی ہے جس قسم کی زندگی ہو گی اسی کے مطابق موت ہو گی.(۱) فَالْاَوَّلُ مَاھُوَ بِـاِزَاءِ الْقُوَّۃِ النَّامِیَّۃِ الْمَوْجُوْدَۃِ فِی الْاِنْسَانِ وَالْحَیَوَانَاتِ وَالنَّبَاتِ.انسان.حیوانات اور نباتات میں نشوونما کا رُک جانا موت کہلاتا ہے جیسے يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الرّوم :۲۰) میں اشارہ فرمایا ہے (۲) اَلثَّانِیْ ، زَوَالُ الْقُوَّۃِ الْحَاسَّۃِ احساس کا زوال بھی موت کہلاتا ہے جیسے حضرت مریم علیھا ا لسلام کا قول يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا (مریم :۴ ۲) ہے کہ اے کاش میں اس سے پہلے کی بے حس ہو چکی ہوتی (۳) زَوَالُ الْقُوَّۃِ الْعَاقِلَۃِ زوال عقل یعنی جہالت بھی موت کہلاتی ہے جیسے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ (الانعام :۱۲۳) (۴) اَلرَّابِعُ الْحُزْنُ الْمُکَدِّرَۃُ لِلْحَیٰوۃِ.ایسے غم جو زندگی کو دوبھر کر دیں جیسے فرمایا.يَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ (ابراہیم :۱۸).(۵) اَلْخَامِس.اَلْمَنَامُ نیند.لسان میں ہے وَقَدْ یُسْتَعَارُ الْمَوْتُ لِلْاَحْوَالِ الشَّاقَّۃِ کَالْفَقْرِ وَالذُّلِّ وَالسُّؤَالِ وَالْھَرَمِ وَالْمَعْصِیَۃِ.کبھی موت کا لفظ استعارۃً تکلیف دِہ حالتوں پر بھی جیسے فقر.ذ ّلت.سوال.بڑھاپا اور معصیت ہیں بولا جاتا ہے.تَشْکُرُوْن.شَکَرَ کے لئے دیکھیں حَلِّ لُغَات آیت نمبر۵۳ سورۃ ھذا.تفسیر.ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ سے مراد جہالت کے بعد علم اور تلخ زندگی کے بعد آرام مہیا کرنا ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ.آیت ما قبل کے ساتھ اس کے یہ معنے ہیں کہ ہم نے ذلّت و تکلیف کے بعد تمہاری حالت کو ترقی دی اور تمہیں معزّز بنایا.پہلی آیت کے الفاظ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ درآنحالیکہ تم دیکھتے تھے.ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مُردے نہیں تھے.حلّ لغات میں موت کے مندرجہ ذیل چھ معنے لغت سے بتائے جاچکے ہیں (۱) قوت نشوونما کا زائل ہو جانا (۲) قوتِ حس کا مر جانا (۳) قوتِ اِدراک کا نہ ہونا یعنی جہالت
Page 103
۴) تکالیف اور دُکھوں والی زندگی.تلخ زندگی(۵) نیند(۶)رُوح کاجسم عنصری سے جدا ہونا.ان مذکورہ معنوں میں سے یہاں صرف ۳،۴ چسپاں ہوتے ہیں.یعنی قوتِ ادراک کا نہ ہونا اور زندگی کا تلخ ہو جانا.اور آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ حقیقی طور پر مر جانے کے بعد زندہ کئے گئے تھے بلکہ آیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس عذاب کا ذکر کیاگیا تھا ہم نے اسے دُور کر کے پھر تم پر فضل کرنا شروع کر دیا اور پہلے عذاب کی وجہ سے جو موت کی سی حالت تم پر طاری ہو گئی تھی اس کو ایک نئی روحانی اور دنیوی زندگی سے بدل دیا.بعض مسلمان مفسّرین نے اس کے معنے رُوح کے جسم سے خارج کرنے کے لئے ہیں لیکن حقیقی موت انہوں نے بھی مراد نہیں لی چنانچہ اس آیت کے متعلق قتادہ جو مشہور مفسّر قرآن ہیں ان کا یہ قول قرطبی نے نقل کیا ہے کہ مَاتُوْا وَذَھَبَتْ اَرْوَاحُھُمْ ثُمَّ رُدُّوْا لِاِسْتِیْفَاءِ اٰجَالِھِمْ (تفسیرقرطبی زیر آیت ھذا ) یعنی حضرت قتاوہ فرماتے ہیں وہ مر گئے اور ان کی رُوحیں نکل گئیں پھر ان کی رُوحیں واپس لائی گئیں تاکہ وہ اپنی مقدّر زندگی کے باقی دن اس دنیا میں پورے کریں.ابن کثیر نے ربیع ابن انس سے بھی یہی تفسیر بیان کی ہے.(تفسیرابن کثیرزیر آیت ھذا) ان الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت قتادہ کے نزدیک وہ حقیقی موت نہیں تھی.کیونکہ حقیقی موت تو زندگی کے دن پورا کر لینے کے بعد آتی ہے.زندگی کے دن پورے ہونے سے پہلے جو رُوح نکلے گی وہ تو عارضی طور پر ہی نکلے گی.بعض نے کہا ہے کہ موت سے مراد حرکت کا بند ہونا ہے چنانچہ لکھا ہے وَ قِیْلَ مَاتُوْا مَوْتَ ھُمُوْدٍ یَعْتَبِرُبِہِ الْغَیْرُ ثُمَّ اُرْسِلُوْا (تفسیرقرطبی زیر آیت ھذا) یعنی وہ اس طرح مر گئے کہ حرکت وغیرہ بند ہو گئی اور ایسی حالت اُن کی ہو گئی کہ اس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کر سکیں.پھر ان کو کھڑا کر دیا گیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ عَلَّمْنَاکُمْ مِنْ بَعْدِ جَھْلِکُمْ (تفسیرقرطبی زیر آیت ھذا ) اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہاری جہالت کے بعد تمہیں علم دیا.یعنی تم نے یہ جو جاہلانہ سوال کیا تھا کہ خدا ہم کو سامنے نظر آ جائے اس سے تمہاری روحانیت مر گئی تھی اور تم پر خدا تعالیٰ کی ناراضگی نازل ہوئی تھی.ہم نے پھر اس ناراضگی کو دُور کر دیا اور تم کو صحیح رُوحانی علم عطا فرمایا جس کی وجہ سے تم کو ایک نئی روحانی زندگی مل گئی.یہ معنی ہمارے کئے ہوئے معنوں کے بہت قریب ہیں.بچھڑے کی پرستش کرنے والوں پر جو عذاب نازل ہوا اس سے وہ حقیقی موت نہ مرے بعض مفسّرین نے اِس عذاب کا تعلق پہلے بچھڑے کی پوجا سے قائم کیا ہے مگر یہ درست نہیں.یہاں واضح الفاظ میں بنی اسرائیل کا ایک اور جرم مذکور ہے یعنی ان کا یہ قول کہ ہم کبھی بھی موسیٰ ؑ کی بات نہیں مانیں گے جب تک خدا ہم کو سامنے نہ نظر آ جائے.دوسرے یہاں جو سزا مذکور ہوئی ہے وہ بچھڑے والی سزا سے مختلف ہے پس معلوم ہوا کہ وہ
Page 104
واقعہ اَور ہے اور یہ واقعہ اَور ہے.اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہلَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً (البقرة: ۵۶) میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر ہے نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام پر ایمان لانے کا.اور مراد یہ ہے کہ جب تک خدا ہمیں نظر نہ آ جائے ہم تیری فرمانبرداری نہیں کریں گے.پس وہ اس موقع پر موسیٰ ؑ کی نبوت میں شک نہیں کرتے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے اس وقت تک انکار کرتے ہیں جب تک کہ ان کو وہی درجہ نہ دے دیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ سے بالمشافہ گفتگو کرنے سے حاصل تھا.یہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ موت سے مراد درحقیقت حقیقی موت نہیں اور حق یہ ہے کہ اگر حقیقی موت مراد لی جائے تو اوّل تو قرآن کریم کی دوسری آیات کی تردید ہوتی ہے جن میں اِس دنیا میں مُردوں کے واپس آنے سے اِنکار کیا گیا ہے مثلاً سورۂ مؤمنون میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ.لَعَلِّيْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا١ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآىِٕلُهَا١ؕ وَ مِنْ وَّرَآىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.(المؤمنون: ۱۰۰،۱۰۱) یعنی جب اُن میں سے کسی پر موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اے میرے ربّ مجھے لَوٹا دے تاکہ مَیں دنیا میں واپس جا کر اپنے اموال و جائداد کے ذریعہ سے اچھے عمل کروں.فرماتا ہے ہرگز نہیں.ہرگز نہیں ایسا کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا.یہ صرف ایک بات ہے جو وہ مُنہ سے نکال رہا ہے یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی.ان مرنے والوں کے پیچھے تو ایک برزخ ہے جو قیامت کے دن تک چلی جائے گی.اس آیت سے ظاہر ہے کہ مرنے والا اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا.جو حیات انسان کو ملے گی اس کی تکمیل اس دن ہو گی جبکہ اگلے جہان کی زندگی کا نیا دَور شروع ہو گا.اس کے علاوہ عقلی اعتراضات بھی اس دوبارہ زندگی پر پڑتے ہیں مثلاً ایک اعتراض یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مر کر دوبارہ زندہ ہو گا تو اس کا ایمان طوعی نہیں ہو گا بلکہ اضطراری ہو جائے گا.اس دنیا میں ایمان کے لئے ایک حد تک اخفاء کا ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے انبیاء کے معجزات میں ایک حد تک اخفاء کا پہلو قائم رکھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے لوگ انبیاء کے نہایت ہی کھلے اور ظاہر معجزات پر بھی اعتراضات کرتے چلے جاتے ہیں.اگر دنیا کی چیزوںکے مشاہدہ کی طرح ایمان کے معاملات بھی سائنٹفک تجربات کے اصول پر آ جائیں تو اُن پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ رہے اور کافر و مومن ان کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور ایمان سے جو فائدہ مطلوب ہے وہ جاتا رہے.پس مُردے کا واپس دنیا میں آنا ایمان کی غرض کو باطل کرتا ہے اور کم سے کم اُس زندہ ہونے والے کے لئے تو ایمان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی.یہ شبہ پہلے مفسرین کے دلوں میں بھی پیدا ہوا ہے چنانچہ علّامہ ماوردی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایسے مُردے جو واپس آئیں آیا وہ اعمال کے مکلّف
Page 105
ہوں گے یا نہیں کیونکہ وہ تو مر چکے اور حقیقت کا انکشاف ان پر ہو چکا چنانچہ وہ لکھتے ہیں وَ اخْتُلِفَ فِیْ بَقَاءِ تَکْلِیْفِ مَنْ اُعِیْدَ بَعْدَ مَوْتِہٖ وَ مُعَایَنَۃِ الْاَحْوَالِ الْمُضْطَرَّۃِ اِلَی الْمَعْرِ فَۃِ عَلٰی قَوْلَیْنِ اَحَدُھُمَا بَقَاءُ تَکْلِیْفِھِمْ لِئَلَّا یَخْلُوَ عَاقِلٌ مِنْ تَعَبُّدٍ.اَلثَّانِیْ.سَقُوْطُ تَکْلِیْفِہِمْ مُعْتَبِرًا بِا لْاِسْتِدْلَالِ دُوْنَ الْاِضْطِرَارِ(قرطبی زیر آیت ھذا ) ماوردی کہتے ہیں کہ جو لوگ موت کے بعد زندہ ہوں اور اُن حالات کو آنکھوں سے دیکھ لیں جو انسان کو معرفت پر مجبور کر دیتے ہیں تو ان کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا عبادت اُن پر واجب رہتی ہے یا نہیں.ایک قول تو یہ ہے کہ اُن پر واجب رہتی ہے تاکہ کوئی عاقل بھی عبادت سے باہر نہ رہے یعنی جہاں تک اُن کے نفس کا تعلق ہے جسمانی عبادات اُن کو فائدہ نہیں دیتیں لیکن اس لئے کہ دوسرے لوگوں کو ٹھوکر نہ لگے اُن کے لئے بھی عبادت کرتے رہنا ضروری ہے.دوسرا قول یہ ہے کہ اُن پر سے عبادات ساقط ہو جاتی ہیں کیونکہ اعمال کے لئے مکلّف کیا جانا اسی وقت تک مفید ہو سکتا ہے جبکہ اعمال کی بنیاد استدلال پر ہو.نہ کہ ایسی حالت پیدا ہو جائے جو کہ مضطر اور مجبور کر کے ان پر عمل کروائے.اس شبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ پرانے مفسّرین اور علماء کے دلوں میں بھی یہ شبہ موجود تھا کہ مُردوں کا اس دنیا میں واپس آنا شریعت کے بعض اَور مسائل کو باطل کر دیتا ہے گو انہوں نے اِس شبہ کے ازالہ کے لئے کوشش کی ہے مگر جیسا کہ ظاہر ہے وہ کوشش ناکام رہی ہے اور تسلّی بخش نہیں.پس حقیقت یہی ہے کہ حقیقی مُردے اِس دنیا میں زندہ ہو کر واپس نہیں آتے اور اس آیت میں یا اَور جس آیت میں بھی مُردوں کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے اس کے معنے حقیقی احیاء موتیٰ کے نہیں ہو سکتے بلکہ یا روحانی مرد ے کا زندہ ہونا.یا مُردے جیسی حالت کو پُہنچے ہوئے مریض کا اچھا ہونا.یا گری ہوئی قوم کا دوبارہ ترقّی پانا یا کفر کی حالت کا ایمان کی حالت سے بدل جانا یا اور اسی قسم کے کسی تغیّر کا پایا جانا ہی مراد ہے.وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى ١ؕ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لئے مَن اور سَلویٰ اتارے.(اور کہا کہ) كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ١ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْا ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ.اور انہوں نے( نافرمانی کرکے ) ہمارا نقصان نہیں کیا
Page 106
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ۰۰۵۸ بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے.حلّ لُغات.ظَلَّلْنَا.ظَلَّلَ سے متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے اور ظَلَّلَہٗ تَظْلِیْلًاکے معنے ہیں غَشِیَہٗ وَ اَلْقٰی عَلَیْہِ ظِلَّہٗ اس کو ڈھانپ لیا اور اس پر اپنا سایہ ڈال دیا اور جب ظَلَّلْنَا عَلَیْکُمُ الْغَمَامَ کہیں تو مطلب یہ ہو گا کہ سَخَّرْنَاہُ لِیُظِلَّھُمْ ہم نے بادل کو ان پر سایہ کرنے کی خدمت پر لگا دیا.(اقرب) اَلْغَمَامُ.اَلْغَمَامُ کے معنی اَلسَّحَابُ بادل وَقِیْلَ الْاَ بْیَضُ اور بعض نے کہا ہے کہ غمام سفید بادلوں کو ہی کہیں گے اور بادل کو غَمَام کہنے کی یہ وجہ ہے کہ غَمَّ کے معنی ڈھانپنے کے ہیں اور بادل بھی آسمان کو ڈھانپ لیتا ہے.اس کی جمع غَمَائِمُ آتی ہے.(اقرب) ٔ اَلْمَنُّ.مَنَّ یَمُنُّ کا مصدر ہے چنانچہ کہتے ہیں مَنَّ (عَلَیْہِ بِالْعِتْقِ وَغَیْرِہٖ یَمُنُّ )مَنًّا اَیْ اَنْعَمَ عَلَیْہِ بِہٖ مِنْ غَیْرِ تَعْبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ اصْطَنَعَ عِنْدَ ہٗ صَنِیْعَۃً وَ اِحْسَانًا کسی پر اس کی محنت و مشقت کے بغیر انعام کیا اور اس کے ساتھ نیک سلوک کیا احسان کیا نیز اَلْمَنُّ کے معنے ہیں کُلُّ مَا یَمُنُّ اللہُ بِہٖ مِمَّا لَا تَعَبَ فِیْہِ وَلَانَصَبَ ہر وہ چیز جو اﷲ تعالیٰ کسی شخص کو محنت اور مشقت کے بغیر عطا فرماوے وہ مَنّ کہلاتی ہے کُلُّ طَلٍّ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ عَلٰی شَجَرٍ اَوحَجَرٍ وَیَحْلُوْ وَ یَنْعَقِدُ عَسَلًا وَیَجِفُّ جِفَانَ الصَّمْغِ کَالسِّیْرَخُشْتٍ وَ التُّرَنْجَبِیْنَ.ہر وہ شبنم جو آسمان سے درختوں اور پتّھروں پر اُترتی ہے اور وہ میٹھی ہوتی ہے اور پھر شہد کی طرح گاڑھی ہو جاتی ہے اور گوند کی طرح سوکھ کر ایسی ہو جاتی ہے مثلاً شیر خشت اور ترنجبین (اقرب) اَلسَّلْوٰی.اَلسَّلْوٰی کے معنی ہیں(۱) اَلْعَسْلُ شہد(۲)کُلُّ مَاسَلَاکَ ہر وہ چیز جو تسلّی کا موجب ہو.(۳) طَائِرٌ اَبْیَضُ مِثْلُ السَّمَانِیْ بٹیر کی مانند سفید پرندے ( مفرد سَلْوَاۃٌ آتا ہے ) وَقِیْلَ اَلسَّلْوٰی.أَللَّحْمُ اور بعض نے کہا ہے کہ سَلْوٰی گوشت کو کہتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے لِاَنَّہٗ یُسَلِّی الْاِنْسَانَ عَنْ سَائِرِالْاِدَامِ کہ جب گوشت دسترخوان پر آئے تو یہ باقی سالنوں کی جگہ کافی ہو جاتا ہے اور دوسرے سالنوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی (اقرب) مفردات میں ہے کہ اَلسَّلْوٰی اَصْلُہَامَایُسَلِّی الْاِنْسَانَ.سَلْوٰی کے اصل معنے تو اس چیز کے ہیں جو انسان کو تسلّی دے.یُقَالُ سَلَیْتُ عَنْ کَذَا اِذَا زَالَ عَنْکَ مَحَبَّتُہٗ چنانچہ سَلَیْتُ عَنْ کَذَا کے معنی ہیں کہ مَیں فلاں مرغوب چیز کو بھول گیا اور دل میں اس کی خواہش نہ رہی ( مفردات) پس اقرب
Page 107
والے نے جو گوشت کو سَلْوٰیکہا ہے وہ اس لئے ہے کہ گوشت کے ملنے کی وجہ سے دوسرے سالنوں کی طرف رغبت نہیں رہتی.طَیّبَاتٌ.طَیِّبَاتٌ.طَیِّبَۃٌ کی جمع ہے اور طَیِّبَۃٌ طَیِّبٌ سے مؤنث کا صیغہ ہے جو طَابَ سے بنا ہے اور طَابَ الشَّیْءُ کے معنی ہیں لَذَّ وَ زَکَا وَ حَسُنَ وَحَلَا وَجَلَّ وَجَادَ کہ کوئی چیز مرغوب ،پاکیزہ ،عمدہ، خوبصورت، دلربا اور دل لبھانے والی ہو گئی ( اقرب) طَیِّبٌ کے معنے ہیں ذُوالطِّیْبَۃِ جس کے اندر لفظ طَابَ کے معنی کے ضمن میں بیان شدہ تمام صفات ہوں.خِلَافُ الْخَبِیْثِ جو گندہ ،ردّی اور فاسد نہ ہو.اَلْحَلَالُ.حلال (اقرب) مفردات میں ہے اَصْلُ الطَّیِّبِ مَا تَسْتَلِذُّہُ الْحَوَاسُ وَمَا تَسْتَلِذُّہُ النَّفْسُ کہ طیّب کے اصل معنے تو یہ ہیں کہ جس سے حواس انسانی اور نفس انسانی لذّت اُٹھائے.وَالطَّعَامُ الطَّیِّبُ فِی الشَّرْعِ مَاکَانَ مُتَنَاوَلًا مِنْ حِیْثُ مَایَجُوْزُ وَ بِقَدْرِمَایَجُوْزُ وَمِنَ الْمَکَانِ الَّذِیْ یَجُوْزُ اور شریعت کی رو سے طیّب اس چیز کو کہیں گے جو جائز طریقہ اور مناسب و جائز اندازے کے مطابق اور جائز جگہ سے حاصل کی جائے.(مفردات) رَزَقْنٰـکُمْ.رَزَقْنَا رَزَقَ سے متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے اور اَلرِّزْقُ (جو رَزَقَ کا مصدر ہے) کے معنے ہیں.اَلْعَطَاءُ.عطا کرنا.دینا.جیسے کہتے ہیں رُزِقْتُ عِلْمًا کہ مجھے علم دیا گیا ہے.اور اس کے ایک معنی حصہ کے بھی ہیں جیسے وَ تَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ (الواقعہ:۸۳) کہ تم نے اپنے ذمہ یہ کام لگا لیا ہے کہ رسول اور خدا کی باتوں کا انکار کرتے ہو (مفردات) اقرب الموارد میں ہے.اَلرِّزْقُ.مَایُنْتَفَعُ بِہٖ ہر وہ چیز جس سے نفع اُٹھایا جائے.اور رَزَقَہُ اللّٰہُ ( یَرْزُقُ) رِزْقًا کے معنے ہیں اَوْصَلَ اِلَیْہِ رِزْقًا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے ایسی اشیاء عطا فرمائیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکے.رزق اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو غذا کے طور پر استعمال کی جائے (مفردات) ظَلَمُوْنَا.ظَلَمَ کے لئے دیکھو حَلِّ لُغَات سورۃ ہذاآیت نمبر ۵۲.تفسیر.بائبل میں بنی اسرائیل پر دشت میں بادلوں کے سایہ کرنے کا ذکر گنتی باب ۹ آیت ۱۷ تا ۲۲ میں لکھا ہے.’’ اور جب مسکن پر سے بدلی اُٹھائی جاتی تھی تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے اور جہاں بدلی آ کے ٹھہرتی تھی وہاں بنی اسرائیل خیمے کھڑے کرتے تھے.خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے اور خداوند کے حکم سے مقام کرتے تھے.اور جب تک کہ بدلی مسکن پر ٹھہرتی تھی خیموں میں رہتے تھے اور جب بدلی مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہری رہی تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم پر لحاظ کرتے رہے اور کوچ نہ کیا اور ایسے ہی جب بدلی جب تھوڑے دنوں تک مسکن پر رہی وے خداوند کے حکم سے اپنے خیموں میں رہے اور خداوند
Page 108
کے حکم سے انہوں نے کوچ کیا.اور جب شام سے صبح تک بدلی ٹھہری رہی اور صبح ہوتے ہوئے بلند ہوئی تو وہیں انہوں نے کوچ کیا.جب بدلی بلندہوتی خواہ دن ہوتا خواہ رات وے کوچ کرتے تھے اور جب بدلی مسکن پر ٹھہری رہتی خواہ دو دن، خواہ ایک مہینہ، خواہ ایک برس.بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہ کرتے پر جب وہ بلند ہوتی تب وہ کوچ کرتے.نیز دیکھو.(گنتی باب ۱۰ آیت ۳۴ و خروج باب ۴۰ آیت ۳۴ تا ۳۸) ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ بنی اسرائیل خیمہ زن ہوتے تھے وہاں بادل پھیل کر سایہ کر لیتے تھے.جب اُن کے سفر پر روانہ ہونے کا دن آتا تو پھر بادل اوپر چڑھ جاتے لیکن قرآن شریف کے الفاظ اور سیاق سے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادلوں کے ِگھر آنے سے بارش ہونا مراد ہے کیونکہ عام طور پر برسنے والے بادل گھنے اور تاریک ہوتے ہیں.پس یا تو قرآن کریم اس جگہ بائبل کے بیان کی تردید کرتا ہے یا دوسرے واقعہ کا بیان کرتا ہے جس کا ذکر بائبل میں نہیں.میرے نزدیک اس جگہ تردید ہی ہے کیونکہ بائبل نے جس طرح بادلوں کا ذکر کیا ہے وہ غیر معقول اور ساتھ ہی غیر ضروری بھی ہے.بنی اسرائیل کو کسی جگہ ٹھہرانے کے لئے انہیں چاروں طرف سے بادلوں سے گھیر لینے کی کیا ضرورت تھی موسیٰ علیہ ا لسلام کو الہام ہو جانا کافی تھا.بادلوں سے سایہ کرنے سے مراد بنی اسرائیل کو بارش کے ذریعہ پانی مہیا کرنا بادلوں کے ساتھ قرآن شریف دو اور کھانے والی چیزوں مَنْ وَ سَلْوٰی کا بھی ذکر فرماتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ویرانے جنگل میں پانی کی طرح کھانے کی بھی قلّت تھی.اﷲ تعالیٰ گھنے بادل بھیج کر ان کی پیاس بجھاتا تھا اور مَنّ و سَلْوٰی سے اُن کی بھوک دور فرماتا تھا.اﷲ تعالیٰ اپنے بندوں کی تکالیف دور کرنے اور ان کی آسائش و آرام بڑھانے کے لئے خاص انعامات ظاہر فرماتا ہے.یہ اُس کی عادت زمانۂ گزشتہ ہی کے لئے نہ تھی بلکہ اس زمانہ میں بھی وہ اپنے مقبول بندوں کے لئے انعام و برکات اسی طرح نازل فرماتا ہے اِس کے یہ معنے کرنے کہ ہر وقت ان پر بادلوں کا سایہ رہتا تھا درست نہیں کیونکہ ہر وقت اَبَر کا رہنا تو بجائے نعمت کے مصیبت ہے.بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے تھے.کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی.اﷲ تعالیٰ ان پر بادل برساتا تھا جس سے وہ پیاس بجھاتے تھے اور دوسری ضرورتیں پوری کرتے تھے.مَنّکی تشریح مَنّ کے لغوی معنے اوپر لکھے جا چکے ہیں.ترنجبین یا ہر وہ چیز جو بغیر محنت کے ملے اُسے مَنّ کہتے ہیں.یہ اپنے مخصوص معنوں میں گوند کی قسم کی ایک چیز ہے جو بعض درختوں پر جم جاتی ہے اور مزے میں شیریں ہوتی ہے.بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ترنجبین ہے.ترنجبین کے نام پر جو دوا ہندوستان میں مِلتی ہے اُس میں سے اکثر
Page 109
مصنوعی ہوتی ہے.اصل مَنّ دشتِ سیناء.شام اور عراق کے بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے.ابھی کچھ دن ہوئے ایک دوست عراق سے میرے لئے مَنّ تحفۃً لائے تھے.مصنوعی بھی اور اصلی بھی.مصنوعی تو ویسی ہی تھی جیسے ہندوستان میں ترنجبین ہوتی ہے لیکن اصلی مَنّ کائی کے پتّوں کا ایک ڈلاسا معلوم ہوتا تھا.مجھے اس دوست نے بتایا کہ یہ رطوبت ان چھوٹے چھوٹے پتّوں سے جو درختوں کی جڑوں پر اُگ آتے ہیں ملی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ اِن پتّوں سمیت اسے اکٹھا کر لیتے ہیں پھر گرم کر کے چھان لیتے ہیں اور پتّوں کو پھینک دیتے ہیں.جو شیرینی ان میں سے نکلتی ہے اس میں بادام اور پستہ وغیرہ ڈال کر اُس کی مٹھائی بنانے کا عربوں میں رواج ہے.مَیں نے بھی اسے صاف کروایا تو اس میں سے شہد کی طرز کی ایک چیز نکلی.رنگ اس کا بھُورا سا تھا.من ملنے کا ذکر بائبل میں مَنّ کا ذکر بائبل میں خروج باب ۱۶ آیت ۱۳ تا ۱۵ میں آتا ہے وہاں لکھا ہے.’’ اور صبح کو لشکر کے آس پاس اوس پڑی اور جب اَوس پڑ چکی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز ایسی سفید جیسے برف کا چھوٹا ٹکڑا زمین پر پڑی ہے اور بنی اسرائیل نے دیکھ کے آپس میں کہا کہ مَنّ ہے کیونکہ انہوں نے نہ جاناکہ وہ کیا ہے تب موسیٰ نے اُنہیں کہا کہ یہ روٹی ہے جو خداوند نے کھانے کو تمہیں دی ہے.‘‘ اس حوالہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز زمین پر گری تھی لیکن جیسا کہ مَیں نے بتایا ہے عرب اور شام کے لوگ جہاں یہ مَنّ پیدا ہوتی ہے اُن کی یہ گواہی ہے کہ یہ درختوں پر گری ہوئی یا درختوں سے نکلی ہوئی ایک رطوبت ہے جو شیریں ہوتی ہے.ممکن ہے دشت ِ سیناء میں جن درختوں کی جڑوں میں سے یہ مَنّ نکلتی ہو یا جن کی جڑوں پر گرتی ہو اُن پر کائی نہ ہوتی ہو اور مصفّٰی ڈلیاں الگ الگ جم جاتی ہوں بہر حال جو مَیں نے دیکھی ہے اور جو عراق میں پائی جاتی ہے وہ تو کائی کے ساتھ مِلی ہوئی ہے اور اسے گرم کر کے الگ کیا جاتا ہے.بنی اسرائیل کو مَنّ ملنے سے مراد مَنّ کے معنٰی جیسا کہ مَیں بتا چکا ہوں بلا محنت و مشقت ملنے والی چیز کے بھی ہیں اور ان معنوں کے لحاظ سے اِس لفظ کا تمام ایسی چیزوں پر اطلاق ہو سکتا ہے جو بغیر محنت کے مِل جاتی ہیں چنانچہ حدیث میں آتا ہے.اَلْکَمْأَۃُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِیْ اَنْزَلَ اللہُ عَلٰی مُوْسٰی (مسلم کتاب الأشربۃ باب فضل الکمأۃ) یعنیُ کھمبی بھی مَنّ کی اُن اقسام میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں.اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ مَنّ کسی چیز کا نام نہیں بلکہ کئی ایسی چیزیں جو کھانے کے کام آتی ہیں اور جنگلوں میں خود رَو یا بغیر کوشش کے پڑی ہوئی مِل جاتی ہیں اُن سب کو مَنْ کہتے ہیں.پس ُکھمبی بھی مَنّ کی قسموں میں سے ہے.
Page 110
ترنجبین بھی مَنّ کی قسموں میں ہے.اسی طرح بیریا پیلو وغیرہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے کام میں آسکتی ہیں.پیٹ بھرتی ہیں.غذائیت کا کام دیتی ہیں.جہاں جہاں پائی جاتی ہیں کثرت سے مِل جاتی ہیں اور جنگلوں میں چلنے والے قافلے بعض دفعہ ہفتوں ان پر گزارہ کرتے ہیں.معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ہجرت کے سالوں میں اﷲ تعالیٰ نے کثرت سے یہ اشیاء جنگل میں پیدا کر دی تھیں جن کو بنی اسرائیل کھاتے تھے اور پیٹ بھر لیتے تھے.اسی طرح آٹا اور چاول وغیرہ جو خرید کرنے والی اشیاء ہیں ان کی اُنہیں بہت کم ضرورت پیش آتی تھی.سَلْوٰی.بنی اسرائیل کو سلوٰی ملنے سے مراد سَلْوٰی کے معنے بھی مَنّ کی طرح ایک عام ہیں اور ایک خاص.اس کے عام معنے تو ہر اُس چیز کے ہیں جو تسلّی دینے والی ہو اور خاص معنوں کے لحاظ سے وہ ایک پرندے کا بھی نام ہے جو بٹیر کے مشابہ ہوتا ہے اور شہد کو بھی سلویٰ کہتے ہیں.بائبل میں اس کا ذکر گنتی باب ۱۱ آیت ۳۱ تا ۳۴ میں آتا ہے.وہاں لکھا ہے.’’ تب خداوند کی طرف سے ایک ہوا اُٹھی اور دریا سے بٹیر اُڑا لائی اور انہیں خیمہ گاہ پر اور خیمہ گاہ کے گِرد اگر د اِدھر اُدھر ایک دن کی راہ تک پھیلایا.ایسا کہ وہ زمین پردو ہاتھ بلند ہوا تب لوگ اُس سارے دن اور اُس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی کھڑے رہے اور بٹیر جمع کیاکئے اور جس نے کم سے کم جمع کئے دس خومر (نصف من ) تھے اور انہوں نے اپنے لئے خیمہ گاہ کے آس پاس اُنہیں پھیلا دیا اور ہنوز اُن کے دانتوں تلے گوشت تھا پہلے اس سے کہ وَے اُسے چابیں خداوند کا غصّہ ان لوگوں پر بھڑکا اور خداوند نے ان لوگوں کو بڑی مری سے مارا اور اُس نے اس مقام کا نام قَبَرَاتُ التَّہَا وَہ (حرص کی قبریں) ر کھا کیونکہ انہوں نے اُن لوگوں کو جنہوں نے حرص کی تھی وہیں گاڑا.‘‘ چونکہ بنی اسرائیل مدتوں تک فراعنۂ مصر کی غلامی میں رہے تھے.اﷲ تعالیٰ نے چاہا کہ انہیں جنگل میں آزاد رکھ کر اُن میں جرأت اور بہادری کے اخلاق پیدا کرے.اس لئے بجائے جلد سے جلد کنعان پہنچانے کے اُن کو ایک عرصہ تک دشتِ سینا اور اس کے اِرد گرد کے علاقہ میں رکھا اور اُن کے لئے ایسی غذائیں جو بلا تعب اور بغیر محنت کے ملتی تھیں مہیا فرما دیں.کچھ شیریں، کچھ نمکیں، کچھ ٹھوس، کچھ ہلکی، کچھ پکانے والی، کچھ کچی کھانے والی تاکہ ذوق کو بھی ان سے تسلّی حاصل ہو اور معدہ بھی بھرے اور صحت کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی پوری طرح میسّر آ جائیں.جیسا کہ مَیں بیان کر چکا ہوں مَنّ میں پھل ، کھمبیاں اور ترنجبین وغیرہ شامِل ہیں.اور سَلْویٰ میں پرندے.شہد اور وہ تمام ایسی غذائیں جو کہ قلب کو تسکین دیتی ہیں شامل ہیں.پس بادل نازل کر کے پانی مہیّا فرما دیا
Page 111
گیا.مَنّ نازل کر کے پھل اور سبزی ترکاری کی قسم کی غذائیں مہیّا کر دی گئیں اور سَلْوٰی نازل کر کے اﷲ تعالیٰ نے گوشت کی ضرورت کو مہیّا کر دیا.منّ و سلوٰی کے دیئے جانے کے ساتھ لفظ نزول کا استعمال اور ایک مشکل کا حل یہاں اَنْزَلْنَا کا لفظ بھی غور کے قابل ہے.نُزُوْل کا لفظ اعزازو احترام کے لئے یا غیر معمولی حالات کے مطابق کسی چیز کے مہیّا کرنے کے لئے بولا جاتا ہے.مَنّ اور سَلْویٰ آسمان سے نہیں اُترتے تھے.زمین کی ہی چیزیں تھیں اور زمین پر ہی پیدا ہوتی رہتی تھیں.ان کے لئے نزول کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں اﷲ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لئے یہ چیزیں مہیّا کر دی تھیں.جو لوگ آنے والے مسیحؑ کے متعلق نزول کے الفاظ پڑھ کر قسم قسم کی غلطیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اُنہیں قرآن کریم کے یہ محاورات بھی مدّنظر رکھنے چاہئیں.اگر زمین میں پیدا ہو کر مَنّ و سَلوٰی کے لئے نزول کا لفظ آ سکتا ہے تو زمین میں ہی پیدا ہو کر مسیح کے لئے نزول کا لفظ کیوں نہیں آسکتا.جس طرح مَنّ و سَلوٰی کا غیر معمولی حالات میں مہیّا کر دینا قرآنی اصطلاح میں نزول کہلایا ہے اسی طرح فسق و فجور کے زمانہ میں ایک پاکیزہ نفس مصلح کا پیدا ہو جانا خدائی اصطلاح میں نزول کہلاتا ہے اور مسیح موعودؑ کے لئے بھی انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.اس کے بعد فرماتا ہے.كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ.جو کچھ ہم نے تمہیں طیّبات میں سے دیا ہے اسے کھاؤ یعنی اِس زمانہ میں یہ غذائیں تمہارے لئے نہایت ہی اعلیٰ درجہ کی ہیں.ان کے استعمال سے وہ تمام ضرورتیں جو تمہیں لاحق ہیں پوری ہو جائیںگی.كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ … الخ میں طیّب کے معنے طَیّب کے معنے لذیذ ، پاکیزہ، خوبصورت، میٹھے اور شاندار کے ہوتے ہیں پس کُلُوْا مِنْ طَیّبٰتِ مَارَزَقْنٰـکُمْ کے معنے یہ ہوئے کہ یہ چیزیںاس وقت تمہاری لذّت کے سامان بھی مہیّا کرتی ہیں، تمہارے اخلاق کی درستی کا موجب بھی ہیں.ظاہری شکلوں میں بھی وہ اچھے کھانے ہیں.شیریں و لطیف بھی ہیں اور اپنے فوائد کی عظمت کے لحاظ سے بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہیں پس تم ان کو کھاؤ اور اخلاقِ حسنہ پیدا کر کے اُس عظیم الشّان کام کے لئے تیار ہو جاؤ جو تمہارے لئے مقدّر ہے.مَنّ و سَلوٰی کے بطور انعام ملنے کے متعلق بائبل اور قرآن مجید کا اختلاف اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ مَنّ اور سَلْوٰی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملے تھے پس وہی طیباّت ہیں بلکہ مدحیہ الفاظ ہوں یا ذمّ کے الفاظ سب کے سب نسبتی ہوتے ہیں.ایک ہی چیز ایک وقت میں اچھی ہوتی ہے یا ایک شخص کے لئے
Page 112
اچھی ہوتی ہے لیکن وہی چیز دوسرے وقت میں ُبری ہو جاتی یا دوسرے شخص کے لئےبرُی ہو جاتی ہے.اسی طرح ایک ہی چیز ایک وقت میں ُبری ہوتی یا ایک شخص کے لئے ُبری ہوتی ہے لیکن وہی چیز دوسرے وقت میں اچھی ہو جاتی یا دوسرے شخص کے لئے اچھی ہو جاتی ہے.جن چیزوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے گو وہ عام طور پر بھی اچھی ہیں لیکن بنی اسرائیل کے حالات کے مطابق وہ اس وقت ان کے لئے خاص طور پر طیّب تھیں.ان غذائوں کو چھوڑ کر دوسری غذائوں کے پیچھے پڑنے سے وہ غرض فوت ہوتی تھی جس کے لئے بنی اسرائیل کو جنگل میں رکھا گیا تھا.بائبل میں سے اوپر گنتی باب ۱۱ آیت ۳۱ تا ۳۴ کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بٹیروں کا آنا بطور عذاب کے تھا کیونکہ ان کے کھانے سے بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہوا.قرآن کریم اس کے خلاف کہتا ہے.قرآن کریم اسے احسان بتاتا اور اپنا انعام قرار دیتا ہے اور قرآن کریم کا بیان ہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ جنگل میں غذا مہیا کر دینا اور پھر اس کے کھانے پر عذاب نازل کرنا یہ تو ایک ظلم ہے.اگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا ہو تاکہ بٹیرے آئیں گے تم انہیں نہ کھانا تب بھی کچھ بات تھی اور اگر بنی اسرائیل میں بٹیرہ حرام ہوتا تب بھی کچھ بات تھی مگر وہاں تو سرے سے بٹیروں کی حرمت کا کوئی حکم ہی موجود نہیں.پھر ایک حلال چیز اگر بنی اسرائیل کو مل گئی اور انہوں نے اسے کھانے کا ارادہ کیا (بائبل میں لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے ہی ان پر عذاب آگیا) تو اس پر ناراضگی کیسی اور ناراضگی بھی ایسی کہ جنگل کا جنگل قبروں سے بھر گیا.یہ تو ایک ظلم ہے اور خدا تعالیٰ ظالم نہیں.خود بائبل کے بعض حصے بھی اس خیال کو ردّ کرتے ہیں چنانچہ خروج باب ۱۶ میں لکھا ہے.’’ اور خداوند نے موسیٰ ؑ سے کہا میں نے بنی اسرائیل کا جھنجھلانا سنا.اُنہیں کہہ کہ تم درمیان زوال اور غروب کے گوشت کھاؤ گے اور صبح کو روٹی سے سیر ہو گے اور تم جانوں گے کہ مَیں خداوند تمہارا خدا ہوں اور یوں ہوا کہ شام کو بٹیریں اوپر آئیں اور پڑاؤ کو چھپا لیا اور صبح کو لشکر کے آس پاس اَوس پڑی اور جب اَوس پڑ چکی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول چیز ایسی سفید جیسے برف کا چھوٹا ٹکڑا زمین پر پڑی ہے.‘‘(خروج باب ۱۶آیت ۱۱ تا ۱۴) اِس حوالہ سے پتہ لگتا ہے کہ بٹیرے خدا تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق آئے اور خدا تعالیٰ نے قبل از وقت حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام سے کہا کہ تم ان بٹیروں کو کھانا اور انہیں انعام قرار دیا اور فرمایا کہ ان کے کھانے سے ’’تم جانو گے کہ مَیں خداوند تمہارا خدا ہوں.‘‘ اور بٹیروں کے انعام کو مَنّکے انعام کے ساتھ اکٹھا بیان کیا اور مَنّکے انعام کو ساری بائبل میں انعام ہی قرار دیا گیا ہے کہیں اسے عذاب قرار نہیں دیا گیا.پس گنتی باب۱۱ میں جو کچھ بیان ہوا ہے
Page 113
وہ بعد کے کسی ناواقف مفسّرِ تورات کی جہالت کا نمونہ ہے جس نے اپنے غلط خیالات کو تورات میں شامل کر دیا ورنہ بات وہی ہے جو قرآنِ کریم نے بیان کی یعنی مَنّ بھی بطور انعام کے تھا اور سَلْوٰی بھی بطور انعام کے تھا.وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ...الخکی تشریح وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے.اس میں یہ بتایا ہے کہ ان احسانات کی بھی انہوں نے ناقدری کی اور اس طرح ہمارے انعاموں کو ناشکری کے ذریعہ سے عذابوں کا موجب بنا لیا.فرماتا ہے.بنی اسرائیل ہمارے انعاموں کی ناشکری کر کے یہ سمجھا کرتے تھے کہ گویا انہوں نے خدا تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اﷲ تعالیٰ کو کسی نے کیا نقصان پہنچانا ہے.جو اﷲ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے وہ تو اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے اور جو اس کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے وہ خود اپنے لئے نعمتوں کے دروازے بند کرتا ہے.خدا تعالیٰ کے احکام کو چٹی سمجھنے کا نتیجہ یہ مصیبت دین کو سمجھ کر نہ ماننے والوں میں ہمیشہ پائی جاتی ہے.آج مسلمانوں پر بھی یہی مصیبت آئی ہوئی ہے.نماز،روزہ،حج،زکوٰۃ،قربانی جتنے احکام ہیں وہ انہیں چٹیّ سمجھتے ہیں اگر ان احکام کو پورا کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ پر احسان کر دیا اور اگر ان احکام کو پورا نہیں کرتے تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو خوب دھوکا دیا.حالانکہ اﷲ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں.کسی کی نماز ، کسی کے روزے ، کسی کا حج،کسی کی زکوٰۃ اور کسی کی قربانی سے اسے کیا فائدہ.یہ ساری باتیں تو ہمارے ہی فائدہ کے لئے ہیں.نماز ہمارے فائدہ کے لئے ہے.روزہ ہمارے فائدہ کے لئے ہے.حج ہمارے فائدہ کے لئے ہے.زکوٰۃ ہمارے فائدہ کے لئے ہے.کسی چیزمیں ہمارے قلب کی اصلاح ہے.کسی چیز میں ہمارے فکر کی اصلاح ہے.کسی چیز میں ہمارے جسم کی اصلاح ہے.کسی چیز میں ہمارے تمدّن کی اصلاح ہے.کسی چیز میں ہماری قوم کی سیاست یا اقتصادیات کی اصلاح ہے.پس ان احکام کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں خدا تعالیٰ کا شکر پیدا ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا اور کامیابی کی ترکیبیں بتائیں.ہم مرتے اور تباہ ہوتے تو اُس کا کیا بگڑجاتا.ہم بچ جائیں تو اس کا کیا سنور جاتا ہے مگر جہالت کا بُرا ہو وہ انسان کو ایسے رستوں پر چلاتی ہے جو عقل کے اور دانائی کے مخالف ہوتے ہیں مگر پھر بھی انسان ہیں کہ اُس پر چلے جاتے ہیں.حصہ ٔ آیت وَمَاظَلَمُوْنَا میں بنی اسرائیل کی من و سلوٰی کے متعلق نافرمانیاں کرنے کا ذکر اور اس کی تائید بائبل سے اس حصہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے مَنّ و سَلْوٰی کے متعلق بھی کچھ نافرمانیاں کی تھیں.سَلوٰی کا مضمون تو جیسا کہ مَیں نے بتا دیا ہے بائبل میں بالکل خبط ہو گیا ہے مگر مَنّ کے
Page 114
متعلق ان کی نافرمانی کا پتہ لگتا ہے چنانچہ خروج باب ۱۶ آیت ۱۹،۲۰ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ ا لسلام کا حکم تھا کہ مَنّ کو جمع نہ کیا جائے لیکن وہ لوگ حرص کی وجہ سے اس کو جمع کرتے تھے.اسی طرح ان کو حکم تھا کہ وہ سبت کے دن مَنّ لینے کے لئے نہ نکلیں لیکن وہ پھر بھی گئے اور انہوں نے کوئی نہ پایا ( خروج باب ۱۶ آیت ۲۵ تا ۲۹) ایسی ہی کوئی بے احتیاطی معلوم ہوتاہے انہوں نے سَلوٰی کے متعلق بھی کی ہو گی.شائد اس کا جمع کرنا بھی منع ہو اور انہوں نے اسے جمع کر لیا ہو.بہر حال اِن الفاظ سے کہ وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر نافرمانی انہوں نے ضرور کی یا کم سے کم انہوں نے اس بارہ میںناشکری سے کام لیا چنانچہ قرآن کریم میں آگے چل کر اس بارہ میںان کی ایک ناشکری کا ذکر آتا بھی ہے.وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو کہ) جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو رَغَدًا وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ بافراغت کھاؤ اور( اس کے) دروازے میں پوری فرمانبرداری کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا( کہ ہم) بوجھ ہلکا خَطٰيٰكُمْ١ؕ وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ۰۰۵۹ کرنے کی التجا(کرتے ہیں)(تب )ہم تمہاری خطاؤں کو بالکل معاف کر دیں گے اور ہم محسنوں کو ضرور بڑھائیں گے.حَلّ لُغَات.اَلْقَرْیَۃُ.اَلْقَرْیَۃُ کے معنے ہیں اَلضَّیْعَۃُ جاگیر.جائداد.اَلْمِصْرُالْجَامِعُ بڑا شہر وَقِیْلَ کُلُّ مَکَانٍ اِتَّصَلَتْ بِہِ الْاَ بْنِیَۃُ وَ اتُّخِذَ قَرَارًا.اور بعض کے نزدیک قَرْیَہ ہر اس جگہ پر بولیں گے جہاں چند گھر پاس پاس بنے ہوئے ہوں اور وہاں لوگوں کی رہائش بھی ہو.جَمْعُ النَّاسِ لوگوں کا گروہ (قَرْیٌ کے معنے جمع کرنے کے بھی ہیں چنانچہ کہتے ہیں قَرَیْتُ الْمَاءَ فِی الْحَوْضِ کہ مَیں نے حوض میں پانی جمع کیا.ان معنوں کو مدّنظر رکھتے ہوئے ہر اس جگہ پر جہاں لوگوں کامجمع ہو اس پر قَرْیَۃٌ کا لفظ بولا جائے گا نیز ان معنوں کو مدّنظر رکھ کر خواہ کوئی شہر ہو یا بستی ہر ایک پر قَرْیَۃ کا لفظ بول سکیں گے لیکن بعض نے قَرْیَۃٌ اور مَدِیْنَۃٌ میں فرق کیا ہے اور کہاہے کہ قَرْیَۃٌ اس بستی کو کہیں گے جس کے ارد گرد فصیل نہ ہو اور مَدِیْنَۃٌ اس کو کہیں گے جس
Page 115
کے ارد گرد فصیل ہو).(اقرب) رَغَدًا.رَغَدَ عَیْشُہٗ رَغَدًا کے معنے ہیں طَابَ وَا تَّسَعَ اس کے لئے زندگی کے سامان وسیع طور پر اور بافراغت مہیا ہو گئے.(اقرب) تاج العروس میں ہے.اَلرَّغَدُ.اَلْکَثِیْرُ الْوَاسِعُ الَّذِیْ لَایُعْیِیْکَ مِنْ مَّالٍ اَوْمَآءٍ اَوْ عَیْشٍ اَوْکَلَإٍ ضروریات زندگی کا سہولت اور کثرت کے ساتھ مل جانا رَغَد کہلاتا ہے.(تاج ) اَلْبَابُ.اَلْمَدْخَلُ.اَلْبَابُ کے معنے ہیں کسی جگہ داخل ہونے کا رستہ نیز جس کے ذریعہ سے وہ رستہ بند کیا جائے اسے بھی باب کہتے ہیں.(اقرب) سُـجَّدًا.سُـجَّدًا سَاجِدٌ کی جمع ہے جو سَـجَدَ سے اسم فاعل ہے.اُسْجُدُوْا.امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور اَلسُّجُوْدُ جو (سَجَدَ کا مصدر ہے) کے معنے ہیں اَلتَّذَ لُّلُ عاجزی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا.وَقَوْلُہٗ اُسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ، قِیْلَ اُمِرُوْا بِالتَّذَ لُّلِ لَہٗ وَ الْقِیَامِ بِمَصَالـِحِہٖ وَ مَصَالِحِ اَوْلَادِہٖ یعنی آیت اُسْـجُدُوْا لِاٰدَمَ الخ میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدم کی فرمانبرداری کریں اور اس کے ماتحت چلیں (یعنی اصلاح کا وہ کام جو آدم دنیا میں کریںگے اس میں اس کی مدد کریں اور اس کی قبولیت لوگوں میں پھیلائیں) اور اس کی مدد کریں اور اس کی اولاد کے لئے ممدّ او رمعاون بنیں اَوِاسْجُدُوْالِاَجَلِ خَلْقِ اٰدَمَ.نیز اُسْـجُدُوْا لِاٰدَمَ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آدم کی پیدائش کی وجہ سے اللہ کے حضور سجدہ میں گر جائو.وَقَوْلُہٗ اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اَیْ مُتَذَ لِّلِیْنَ مُنْقَادِیْنَ اور قرآن کریم میں جو یہ آیا ہے کہ تم اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جائو اس کے معنے بھی یہی ہیں کہ تم فرمانبرداری کرتے ہوئے جائو.(مفردات) سَـجَدَ (یَسْجُدُ) سُجُوْدًاکے معنی ہیں خَضَعَ وَ اِنْحَنٰی اُس نے عاجزی کی اور عجز کا اظہار جھکنے سے کیا سَجَدَ الْبَعِیْرُ.خَفَضَ رَأْسَہٗ اونٹ نے اپنا سر نیچا کیا.سَجَدَ تِ السَّفِیْنَۃُ الرِّیَاحَ : اَطَاعَتْہَا وَمَالَتْ بِمَیْلِہَا کشتی نے ہوا کی پیروی کی اور جدھر کو ہوا اُسے لے گئی اُدھر چل پڑی.اہلِ عرب کہتے ہیں فُـلَانٌ سَاجِدُ الْمِنْخَرِ اور مراد یہ ہوتی ہے ذَلِیْلٌ خَاضِعٌ کہ فلاں شخص مطیع ہے اور عاجزی کرنے والا ہے.(اقرب) پس اُسْـجُدُوْا کے معنے ہوں گے اطاعت و فرمانبرداری کرو.حِطَّۃٌ.اَلْـحِطَّۃُ اِسْتَحَطَّ کا اسم ہے اور اِسْتَحَطَّ فُـلَا نًا وِزْرَہٗ کے معنے ہوتے ہیں سَأَلَہٗ اَنْ یَحُطَّہٗ عَنْہُ کہ اس سے یہ خواہش کی کہ اس سے اس کے بوجھ کو اُتار دے حِطَّۃٌ مبتدا مخدوف کی خبر ہے جس کی تقدیر یوں ہوگی.اَمْرُکَ اَوْمَسْئَلَتُنَا حِطَّۃٌ کہ ہماری دعا یہ ہے یا یہ کہ آپ کی شان کے شایان یہ بات ہے کہ آپ ہمارا
Page 116
بوجھ ہلکا کر دیں.(اقرب) مفردات میں ہے کہ حِطَّۃٌ کے معنے ہیں حُطَّ عَنَّا ذُنُوْبَنَا کہ ہمارے گناہوں اور قصوروں کو معاف کر کے ہمارے بوجھوں کو ہم سے اُتار دیجئے.(مفردات) نَغْفِرْ.غَفَرَ سے مضارع متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے اور غَفَرَ الشَّیْ ءَ غَفْرًا کے معنے ہیں سَتَرَہٗ کسی چیز کو ڈھانپ دیا اور غَفَرَاللہُ لَہٗ ذَنْبَہٗ کے معنے ہیں غَطَّی عَلَیْہِ وَ عَفَا عَنْہُ.اﷲ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ پوشی کی اور اس کے گناہوں سے تجاوز کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور جب غَفَرَاللہُ الْاَمْرَبِغُفْرَتِہٖ کہیں گے تو معنے ہوں گے اَصْلَحَہٗ بِمَایَنْبَغِیْ اَنْ یُّصْلَحَ بِہٖ کسی امر کی ان چیزوں سے اصلاح کی جن کے ذریعہ سے اس کی اصلاح ہو سکتی تھی.(اقرب) خَطَایَا.اَلْخَطِیْئَۃُ کی جمع ہے اور اَلْخَطِیْئَۃُ کے معنے ہیں اَلذَّنْبُ.جرُم.قصور.وَقِیْلَ الْمُتَعَمَّدُ مِنْہُ بعض کے نزدیک خَطِیْئَۃٌ اس قصور کو کہیں گے جو جان بوجھ کر کیا جائے.خَطِیْئَۃٌ کا لفظ اِثْمٌ سے عام ہے کیونکہ اِثْمعمدًا ہی ہوتا ہے اور خَطِیْئَۃ عمدًا اور غیر عمدًا ہر دو طرح ہو سکتی ہے.(اقرب) نَزِیْدُ.زَادَ سے مضارع متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے اور زَادَ لازم اور متعدّی ہر دو طرح استعمال ہوتا ہے چنانچہ زَادَ الشَّیْ ءَ کے معنے ہیں نَـمَا کوئی چیز بڑھ گئی اور زَادَالشَّیْ ءَ کے معنے ہیں کسی چیز کو بڑھایا.نیز زَادَ فَـلَانٌ کے معنے ہیں اَعْطَی الزِّیَادَۃَ اس نے کسی کو حق سے زیادہ دیا (اقرب) پس نَزِیْدُ کے معنے ہوں گے (۱) ہم بڑہائیں گے (۲) ہم زیادہ دیں گے.اَلْمُحْسِنِیْنَ.اَحْسَنَ سے اسم فاعل مُحْسِنٌ آتا ہے.مُحْسِنُوْنَ اور مُحْسِنِیْنَ اس کی جمع ہے.اَحْسَنَ اِلَیْہِ وَبِہٖ کے معنے ہیں عَمِلَ حَسَنًا وَ اَعْطَاہُ الْحَسَنَۃَ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا نیز اس کے معنے ہیں اَتَی بِالْحَسَنِ نیک کام کیا اور جب اَحْسَنَ الشَّیْ ئَ کہیں تو اس کے معنے ہوں گے جَعَلَہٗ حَسَنًا کسی چیز کو خوبصورت بنایا.اَحْسَنَ کے ایک معنے عَلِمَہٗ کے ہیںیعنی کسی چیز کو عمدگی سے جانا.چنانچہ کہتے ہیں فُـلَانٌ یُحْسِنُ الْقِرَاءَ ۃَ کہ فلاں شخص اچھی طرح قرا ء ت جانتا ہے.(اقرب) تفسیر.اُدْخُلُوا الْبَابَ سُـجَّدًا.یعنی فرمانبرداری کی حالت میں شہر میں داخل ہو.اور ایسے اخلاق دکھاؤ جو ایک نبی کی امّت کے مناسب حال ہوں تا ان لوگوں پر بُرا اثر نہ پڑے.قُوْلُوْاحِطَّۃٌ سے مراد قُوْلُوْاحِطَّۃٌ سے یہ مراد ہے کہ اپنی کمزوریوں کی معافی کے لئے دعائیں کرتے جاؤ تاکہ تمدّنی زندگی کے بُرے اثرات تمہارے دلوں پر نہ پڑیں.حِطَّۃٌ اِسْتَحَطَّ کا اسم ہے اور اِسْتَحَطَّ کے معنے
Page 117
بوجھ کے گرائے جانے کی درخواست کرنے کے ہیں اور حِطَّۃٌ اس جگہ خبر ہے ایک مبتدا کی جو محذوف ہے اور وہ مبتدا نحویوں کے نزدیک مَسْئَلَتُنَا ہے یعنی ہماری درخواست حِطَّۃٌ کی ہے یا ہمارا سوال حِطَّۃٌ کا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ اے خدا ہماری تجھ سے درخواست ہے کہ ہمارے گناہوں کے بوجھوں کو ہم سے گرا دے اور ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ کر.بنی اسرائیل جس وقت دشتِ سینا میں سے گزر کر کنعان کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں بعض جگہ وہ ایسے قبائل کے پاس سے گزرے تھے جنہوں نے جنگل میں بعض قصبات اور شہر بنائے ہوئے تھے.( دیکھو انسائیکلوپیڈیا ببلیکا زیر لفظ Rephidim) بنی اسرائیل کی افسردگی دُور کرنے کے لئے ان شہروں میں تھوڑا سا وقت گزارنے کی ان کو اجازت بھی مل جاتی تھی ایسے ہی شہروں میں سے کسی ایک قصبہ یا شہر کا یہاں ذکر ہے.قرآن کریم نے اس قصبہ یا شہر کا نام نہیں لیا اور نہ اس کی ضرورت تھی کیونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے خروج کی تاریخ بیان نہیں کرتا وہ تو حوالے کے طور پر صرف ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو اُس کے بیان کردہ مضامین کی تکمیل کے لئے ضروری ہوتے ہیں.پس اُسے تو اُس عبرت سے غرض ہے جو اس واقعہ سے نکلتی ہے نہ کہ ناموں اور تاریخوں سے.غرض فرماتا ہے ایک گاؤں تھا یا قصبہ یا شہر تھا جس میں داخل ہونے کی ہم نے تمہیں اجازت دی اور یہ کہہ دیا کہ اِس شہر میں داخل ہو کر بافراغت کھاؤ یعنی کچھ دن تمدّنی زندگی کے بھی لطف اُٹھا لو ہاں ایک خیال رکھنا کہ شہر میں مومنانہ طور پر داخل ہونا وَقُوْلُوْا حِطَّۃٌ اور دعائیں اور استغفار کرتے جانا تاکہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے شہر کے باشندوں کے بداخلاق سے متأثر نہ ہو جاؤ اگر ایسا کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو چھپا دیںگے یعنی تمہارے دل کا میلان جو گناہوں کی طرف ہے اسے دبا دیںگے اور نیکی کی قوت عطا کر دیںگے.وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ کہہ کر بتا دیا کہ جو کچھ اوپر بیان کیا گیا ہے یہ ادنیٰ انعام ہے ورنہ اگر تم ہمارے حکم پر پوری طرح عمل کرو گے تو ہم تمہیں اس سے بھی بڑھ چڑھ کر انعام دیںگے یعنی صرف تمہارے دل میں گناہ کے مقابلہ کی ہی طاقت نہیں پیدا ہو جائے گی بلکہ اعلیٰ درجہ کی نیکیوں کی قدرت بھی تم کو حاصل ہو جائے گی.نَزِیْدُا لْمُحْسِنِیْنَکے دو معنے زَادَ کے معنے جیسا کہ حَلِّ لُغَات میں بتائے گئے ہیں زیادہ ہونے کے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنے نسلی ترقی کے بھی ہو سکتے ہیں اور انعامات کے بھی ہو سکتے ہیں.پس اس آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے اچھی طرح ہمارے احکام پر عمل کیا تو ہم تمہاری نسل کو اتنی ترقی دیںگے کہ تم سے بھی بڑے بڑے ملک بس جائیں گے اور تم بھی شہروں کے بانی ہو جاؤ گے اور یہ معنی بھی
Page 118
ہو سکتے ہیں کہ تم شہر کے لوگوں کے اموال اور اُن کی اشیاء کو لالچ سے نہ دیکھنا اگر تم نے فرمانبرداری اور استغفار سے کام لیا تو ہم ان قوموں سے بھی زیادہ اموال اور اشیاء تم کو عطا کریں گے.ریورنڈ ویری کا یہ اعتراض کہ سفر بنی اسرائیل کے واقعات قرآنِ مجید نے حقیقی ترتیب سے بیان نہیں کئے اور اس کا جواب ریورنڈویری اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں کہ واقعات کا اس طرح ملا دینا جن میں سے بعض تو دشت میں واقع ہوئے تھے اور بعض ارضِ مقدسہ میں واقع ہوئے اور بعض کہیں بھی واقع نہیں ہوئے اور پھر مزیدبرآں واقعات کو ایک ایسی ترتیب کے ساتھ بیان کرنا جو حقیقی ترتیب سے بالکل مختلف ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب کا نبی ( نَعُوْذُ بِاللہِ مِنْ ذَالِک) بائبل کے واقعات سے بالکل ناواقف تھا.مجھے ریورنڈویری پر ہمیشہ رحم آتا ہے.اس بندۂ خدا نے اپنی زندگی بالکل ہی برباد کر دی.ایک پادری ہونے کی حیثیت سے ان کا فرض تھا کہ وہ بائبل کا مطالعہ سب سے زیادہ کرتے مگر اس کتاب کا مطالعہ انہوں نے بہت کم کیا ہے.اگر وہ بائبل کا مطالعہ غورسے کرتے تو ایک منٹ کے لئے بھی وہ یہ تصوّر نہ کر سکتے کہ بائبل کوئی مستند تاریخی کتاب ہے اور واقعات کو صحیح پیرایہ میں بیان کرتی ہے.خود بائبل کا موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے واقعات کو متضاد بیان کرنا بائبل کے بیانات تو آپس میں اتنے مختلف ہیں کہ کوئی شخص ان بیانات کی موجودگی میں خروج کی کوئی تاریخ لکھ ہی نہیں سکتا اور خود عیسائی مصنّفین خروج کی بیان کردہ تاریخ کو ناقابلِ اعتبار اور ترتیب کے لحاظ سے غلط قرار دیتے ہیں چنانچہ پروفیسر جے.ایف سٹیننگ ( Stanning) ایم اے آکسفورڈ یونیورسٹی لیکچرار انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا میں لکھتے ہیں کہ خروج میں بعض ایسے واقعات جو موسیٰ ؑکے سفر کے آخری حصّہ کے ہیں شروع میں لکھ دیئے گئے ہیں.اسی طرح وہ لکھتے ہیں مارہ کے پانیوں کو میٹھا کرنے کا واقعہ اور مَنّاور سَلْوٰی کے آنے کا واقعہ بھی اپنی اصل جگہ پر بیان نہیں کیا گیا.مَنّ کا واقعہ سینا سے جانے کے بعد ہوا ہے اور بٹیروں کے واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں.اسی طرح گنتی میں بٹیروں کے واقعہ کو سفر کے آخر میں بیان کیا گیا ہے لیکن خروج میں شروع میں بیان کر دیا گیا ہے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Exodus incident in the wilderness ) جیسا کہ میں اوپر نوٹوں میں ایک مثال دے چکا ہوں خروج باب ۱۶ آیت ۱۱،۱۲ میں تو یہ لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تم شام سے پہلے پہلے بٹیروں کا گوشت کھاؤ گے اور اسے اﷲ تعالیٰ کا ایک انعام قرار دیا ہے لیکن گنتی باب ۱۱ آیت ۳۳ میں یہ لکھا ہے کہ بٹیروں کے آنے پر اُن کا گوشت چبانےسے پہلے بنی اسرائیل مر گئے اور تباہ ہو گئے.گویا کتاب خروج تو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی کرتی ہے کہ وہ لوگ
Page 119
بٹیروں کا گوشت کھائیں گے اور بٹیروں کا گوشت ملنے کو ایک انعام قرار دیتی ہے لیکن گنتی کی کتاب کہ وہ بھی موسیٰ کی ہی وحی کہلاتی ہے یہ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے گوشت نہیں کھایا بلکہ گوشت کھانے کا ارادہ کرنے پر ہی اُن پر عذاب آ گیا.اب اِن بیانات میں کون تطبیق دے سکتا ہے اگر قرآن کریم خروج کے بیان کی تصدیق کرے تو پادری صاحبان کہیں گے کہ قرآن کریم نے چونکہ گنتی کے خلاف کہا ہے اس لئے قرآن کو تاریخ کاپتہ نہیں اور اگر وہ گنتی کے بیان کی تصدیق کرے تو پادری صاحبان کہیں گے کہ چونکہ قرآن نے خروج کے خلاف لکھا ہے اِس لئے قرآن کو بائبل کی تاریخ کا پتہ نہیں.اور اگر وہ دونوں کے ہی مطابق بات کہے تو پھر اس کے معنے یہ ہوں گے کہ جیسی غیر معقول تاریخ بائبل کی ہے ویسی ہی غیر معقول تاریخ ( نعوذ باﷲ ) قرآن کریم کی ہو جائے گی.پس قرآن کریم نے گنتی اور خروج کے جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی.اﷲ تعالیٰ کے علم میں جو واقعات تھے وہ اس نے قرآن کریم میں بیان کر دیئے.اگر بائبل کے بتائے ہوئے واقعات صحیح ہیں تو اس نے بائبل کی تصدیق کر دی.اگر بائبل کے بتائے ہوئے واقعات غلط ہیں تو اس نے ان کی تردید کر دی اور اگر کوئی واقعہ عبرت کے لئے بیان کرنا ضروری تھا اوربائبل میں بیان نہیں ہوا تو اس نے بیان کر دیا.کیونکہ خدا تعالیٰ کو بائبل کے مصنّفین کے تتبعّ کی ضرورت نہیں.فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ پھر( ان کی شرارت کو دیکھو کہ) ان ظالموں نے اس بات کے خلاف جوانہیں کہی گئی تھی ایک اور بات بدل فَاَنْزَلْنَاعَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا (کر کہنی شروع کر)دی جس پر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے نافرمان ہونے کے كَانُوْا يَفْسُقُوْنَؒ۰۰۶۰ سبب سے آسمان سے ایک عذاب نازل کیا.حَلّ لُغَات.ظَلَمُوْا.ظَلَمَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ظَلَمَ کے لئے دیکھو حَلِّ لُغَات سورۃ ھٰذاآیت نمبر ۵۲.رِجْزًا.اَلرِّجْزُ کے معنے ہیں اَلْقَذْرُ گند.عِبَادَۃُ الْاَوْثَانِ بتوں کی عبادت.اَلْعَذَابُ.عذاب
Page 120
اَلشِّرْکُ.شرک.(اقرب) رِجْزٌکے اصل لغوی معنے اضطراب اور پے درپے حرکت کرنے کے ہیں چنانچہ اسی بناء پر رِجْزٌ کے معنے زلزلہ کی قسم کے عذاب کے بھی کئے جاتے ہیں اور شرک اور بتوں کی عبادت کے معنے رِجْزٌ کے اس اعتبار سے ہیں کہ جو ایسا فعل کرتا ہے اس کے اعتقاد میں ایک قسم کا اضطراب ہوتا ہے.اَلسَّمَاءُ.آسمان.کُلُّ مَا عَلَاکَ فَاَظَلَّکَ.ہر اوپر سے سایہ ڈالنے والی چیز.سَقْفُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَبَیْتٍ چھت.رَوَاقُ الْبَیْتِ گھرکے سامنے کا چھجہ.ظَہْرُ الْفَرَسِ گھوڑے کی پیٹھ.السَّحَابُ بادل.اَلْمَطَرُ بارش.اَلْمَطَرُ الجَیِّدَۃُ ایک دفعہ کی برسی ہوئی عمدہ بارش.اَلْعُشْبُ سبزہ و گیاہ.(اقرب) یَفْسُقُوْنَ.فَسَقَ سے مضارع جمع غائب کا صیغہ ہے.فَسَقَ سے اسم فاعل فَاسِقٌ آتا ہے اور فَاسِقُوْنَ.فَاسِقِیْنَ.فَسَقَۃٌ.فُسَّاقٌ فَاسِقٌ کی جمع ہیں.فَسَقَ کے معنے ہیں (۱) تَرَکَ اَمْرَ اللّٰہِ اللہ کے حکم کو ردّ کر دیا.(۲) عَصٰی وَجَارَ عَنْ قَصْدِالسَّبِیْلِ نافرمانی کی اور سیدھے راستہ سے ہٹ گیا.چنانچہ کہتے ہیں فَسَقَتِ الرِّکَابُ عَنْ قَصْدِ السَّبِیْلِ کہ قافلہ چلتے چلتے ٹھیک راستہ سے اِدھر اُدھر ہو گیا.(۳) خَرَجَ عَنْ طَرِیْقِ الْحَقِّ حق کے راستہ سے نکل گیا.وَقِیْلَ فَـجَرَ اور بعض لُغت کے ائمہ نے اس کے معنی بدکار ہو گیا کے کئے ہیں.نیز کہتے ہیں.فَسَقَتِ الرُّطَبَۃُ عَنْ قَشْرِھَا اَیْ خَرَجَتْ.کہ کھجور اپنے چھلکے سے باہر نکل آئی.اور جب فَسَقَ فُـلَانٌ مَالَـہٗ کہیں تو معنے یہ ہوں گے کہ اَھْلَکَہٗ وَاَنْفَقَہٗ اس نے مال کو ضائع کر دیا اور خرچ کر دیا.(اقرب) لسان میں ہے اَلْفُسُوْقُ.اَلْـخُرُوْجُ عَنِ الدِّیْنِ.یعنی فسوق دین سے خروج کرنے کا نام ہے اور اَلْفِسْقُ کے معنی ہیں.اَلْعِصْیَانُ وَالتَّرْکُ لِاَ مْرِ اللّٰہِ وَالْخُرُوْجُ عَنْ طَرِیْقِ الْحَقِّ یعنی نافرمانی اور خدا تعالیٰ کے حکم کو ترک کرنے اور سچے راستے سے خروج کا نام فسق ہے.اَلْمَیْلُ اِلَی الْمَعْصِیَۃِ گناہ کی طرف میلان کو بھی فسق کہتے ہیں.نیز لکھا ہے وَتُسَمَّی الْفَأْرَۃُ فُوَیْسَقَۃً لِخُرُوْجِہَا عَلَی النَّاسِ وَ اِفْسَادِ ھَا یعنی چوہے کو فُوَیْسَقَۃ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دُکھ دیتا ہے اور کام خراب کرتا ہے.(لسان) امام راغب فاسق کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اَکْثَرُ مَا یُقَالُ الْفَاسِقُ لِمَنِ الْتَزَمَ حُکْمَ الشَّرْعِ وَ اَقَرَّ بِہٖ ثُمَّ اَخَلَّ بِجَمِیْعِ اَحْکَامِہٖ اَوْ بِبَعْضِہٖ کہ فاسق کا لفظ اکثر اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو پہلے تو شریعت کے احکام کی پابندی کرے اور ان احکام کو درست سمجھنے کا اقرار کرے لیکن بعدازاں تمام احکامِ شریعت کو یا بعض احکام کو ترک کر دے.وَاِذَا قِیْلَ لِلْکَافِرِ الْاَصْلِیِّ فَاسِقٌ فَـلِاَ نَّـہٗ اَخَلَّ بِحُکْمِ مَا اَلْزَمَہُ
Page 121
الْعَقْلُ وَاقْتَضَتْہُ الْفِطْرَۃُ اور جب شریعت کے احکام کے منکر کے لئے فاسق کا لفظ استعمال کریں تو یہ مفہوم مدِّنظر ہو گا کہ اس نے ان احکام کو چھوڑ دیا اور ان کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جن کو عقل لینے کا فتویٰ دیتی تھی اور جن کو تسلیم کرنے کا فطرت تقاضا کرتی تھی.(مفردات) پس فَاسِقٌ کے معنی ہوئے (۱) نافرمان (۲) خدا تعالیٰ کے حکم کو ترک اور ردّ کرنے والا (۳) حق کو قبول کر کے پھر اُسے ترک کر دینے والا.تفسیر.بنی اسرائیل کا خدا تعالیٰ کے حکم قُوْلُوْا حِطَّۃٌ کے ساتھ تمسخر کرنا اور اس کا نتیجہ فرماتا ہے دیکھو تم نے ہمارے اس انعام کی بھی ناقدری کی.ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ تم کچھ دن اپنی تھکان دور کر لو اور تمدّنی زندگی کا لُطف اُٹھا لو لیکن تم نے اس احسان کے ساتھ بھی تمسخر کرنا شروع کر دیا اور ایک ایسی بات کہنی شروع کر دی جو تمہیں نہیں کہی گئی تھی.کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حِطَّۃٌ کہنے کی بجائے جس کے معنے تھے کہ ہمارے گناہ بخش دیئے جائیں حِنْطَۃٌ.حِنْطَۃٌ کہنا شروع کر دیا یعنی ہمیں گندم مل جائے.گندم مل جائے ( یہ مراد نہیں کہ حِنْطَۃٌ کالفظ استعمال کیا.بلکہ جو عبرانی لفظ بھی گندم کے لئے ہے خواہ حِنْطَۃٌ ہو یا کوئی اور ہو وہ استعمال کیا) شہر کے اندر داخل ہونے کے خیال نے ان کے اندر گندم کے گرم گرم نانوں کی حرص پیدا کر دی اور گناہوں کی معافی کا خیال جاتا رہا اور مذاقًا انہوں نے حِنْطَۃٌ حِنْطَۃٌ کہنا شروع کر دیا کہ خدایا ہمیں گندم دلادے.فرماتا ہے اس کی وجہ سے اُ ن پر عذاب نازل ہوا کیونکہ انہوں نے تمسخر سے کام لیا اور اﷲ تعالیٰ سے احکام کی نافرمانی کی.دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے مگر خدا تعالیٰ کے غضب کا موجب ہو گئی.اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی میں انسان صرف سنجیدگی کی وجہ سے ترقی کر سکتا ہے.انسان کتنی ہی عبادتیںکرے، کتنی ہی قومی خدمت بجا لائے لیکن اس کے اندر سنجیدگی نہ ہو تو وہ کبھی بھی روحانی ترقی نہیں کر سکتا اور نہ قوم کے لئے صحیح طور پر مفید ہو سکتا ہے بلکہ ایسے غیر سنجیدہ لوگ بعض دفعہ قوم کو خطرناک تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں.بظاہر حِطَّۃٌ کو حِنْطَۃٌ کہہ دینا ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اگر غور کرو تو نہایت اہم بات ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تمسخر کیا گیاہے.اس قسم کا تمسخر وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں سنجیدگی نہ ہو اور جس کے دل میں سنجیدگی نہیں نہ وہ دین کے لئے مفید ہو سکتا ہے اور نہ دنیا کے لئے مفید ہو سکتا ہے.چھوٹے چھوٹے اشتعال کے مواقع، چھوٹی چھوٹی حرص کے مواقع ایسے آدمیوں کو ملّت اور مُلک سے غدّاری کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں.
Page 122
قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث کو ہنسی اور تمسخر کے موقع پر استعمال کرنے کے متعلق نصیحت آج مسلمانوں کی بھی یہی کیفیّت ہے جو بے دین ہیں وہ تو بے دین ہیں ہی مگر جو دیندار کہلاتے ہیں علماء ہیں یا صوفیاء ہیں وہ بھی دین کی باتوں سے تمسخر کر لیتے ہیں.کہیں بے موقع قرآن کی آیت پڑھ دیں گے، کہیں ہنسی کے مواقع پر حدیث نبوی ؐپڑھ دیںگے حالانکہ اﷲ اور اس کے رسول کا مقام بہت بالا ہے.اُن کی باتوں کو ہنسی اور تمسخر کے موقع پر بیان کرنا نہایت خطرناک بات ہے.یہ چیز دل کو سیاہ کر دیتی، روحانیت کو مار دیتی اور تقویٰ کو کچل دیتی ہے.اس گناہ پر غالب آنے کے لئے کسی بڑی محنت کی بھی ضرورت نہیں.کسی لالچ کو دبانے کا یہاں سوال نہیں.ایک معمولی سی توجہ کی ضرورت ہے.جن لوگوں میں یہ مرض پائی جاتی ہے وہ ایک ذرا سی توجہ سے اِس نقص کو دُور کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ دل کی ایک ایسی اصلاح کر سکتے ہیں جو ان کو بڑے بڑے کاموں کے لئے تیار کر دے.پس خدا کی باتوں اور اس کے رسول کی باتوںمیں ہنسی اور مذاق کوبالکل چھوڑ دو.یہ گناہ بے لذّت ہے اور انسانی دل کو بالکل مردہ کر دیتا ہے.خدا اور اس کے رسول کا ذکر جب بھی آئے اس کے ساتھ دل میں خشیت پیدا ہونی چاہیے جس سے محبت ہوتی ہے اُس کا ذکر کبھی بھی توجہ کھینچے بغیر نہیں رہتا.اپنے ماں باپ سے کوئی شخص تمسخر نہیں کرتا.اپنے ماں باپ کی باتوں سے کوئی شخص تمسخر نہیں کرتا پھر کیوں خدا اور رسول کی باتوں کو ہنسی کے مواقع پر استعمال کیا جائے کیوں خدا اور رسول کے نام کو تمسخر کے طور پر استعمال کیا جائےاور ایک سکینڈ کے مذاق کے لئے عمر بھر کی عبادت کو ضائع کر دیا جائے.اَلْحَذَرْ ثُمَّ الْحَذَرْ.رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ میں رِجْز سے مراد طاعون یا اَولے رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ.عذاب تو جو پیدا ہوا زمین سے ہی پیدا ہوا مگر کہا یہ گیا ہے کہ آسمان سے نازل کیا.یہ الفاظ اُن الفاظ سے بہت زیادہ زبردست ہیں جو مسیح ؑ کے نزول کے متعلق احادیث میں آئے ہیں کیونکہ مسیح موعود کے متعلق کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ آسمان سے نازل ہو گا بلکہ صرف نازل ہونے کے الفاظ ہیں مگر یہاں تو اس عذاب کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا اورر جز سے صحابہؓ اور دیگر اَئمہ نے عام عذاب یا طاعون یا اَولوں کا عذاب مراد لیا ہے چنانچہ شعبی کا قول ہے.اَلرِّجْزُاِمَّا الطَّاعُوْنُ وَ اِمَّا الْبَرَدُ.رِجْز یا طاعون کو کہتے ہیں یا اَولوں کے عذاب کو کہتے ہیں.اور سعید بن جبیر جو مشہور مفسّرِ قرآن ہیںکہتے ہیں ھُوَ الطَّاعُوْنُ اس سے مراد طاعون ہے اور ابن ابی حاتم نے سعدبن مالکؓ.اسامہ بن زیدؓ اور خزُیمہ بن ثابتؓتین صحابہ ؓ سے روایت کی ہے کہ انہوںنے کہا رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے فرمایا کہ اَلطَّاعُوْنُ رِجْزٌ طاعون ہی رجز ہے اور ابنِ جریرؓ نے بھی اسامہ بن زیدؓ سے روایت
Page 123
کی ہے کہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا.اِنَّ ھٰذَا الْوَجْعُ وَ السُّقْمُ رِجْزٌ عُذِّ بَ بِہٖ بَعْضُ الْاُمَمِ قَبْلَکُمْ (ابن کثیرزیر آیت ھذا ) یعنی یہ درد اور بیماری ( طاعون) رِجز ہے جس کے ذریعہ سے تم سے بعض پہلی قوموں کو عذاب دیا گیا.عذاب کے ساتھ لفظ نزول لگانے کی وجہ حالانکہ عذاب تو مادی بیماری سے تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ طاعون تو ایک مادی بیماری ہے.گلٹی جسم میں نکلتی ہے بخار جسم کو چڑھتا ہے اور اسکے سامان اسی طرح اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جس طرح اور بیماریوں اور چیزوں کے اسباب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں مگر پھر بھی اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے ان کے لئے رِجز اُتارا.اگر کہا جائے کہ چونکہ طاعون کا حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس لئے طاعون کی نسبت یہ کہا گیاکہ وہ آسمان سے اُتاری گئی تو میں کہتا ہوں کہ یہی مسیح کا حال سمجھنا چاہیے.کیا طاعون کا حکم آسمان سے اُترتا ہے لیکن جس شخص کو مامور کیا جاتا ہے اس کا حکم آسمان سے نہیں اُترتا.پس اگر طاعون آسمان سے اُتری ہوئی کہلا سکتی ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے مامور آسمان سے اُترے ہوئے نہیں کہلا سکتے باوجود اس کے کہ وہ زمین پر پیدا ہوں.وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو جب) موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے (اسے) کہا کہ اپنا سونٹا فلاں پتھر الْحَجَرَ١ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا١ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ پر مار.اس پر اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے(اور) ہر ایک گروہ نے اپنی اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ١ؕ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا گھاٹ کو پہچان لیا (تب انہیں کہا گیا کہ) اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۰۰۶۱ مفسد بن کر زمین میں خرابی نہ پیدا کرو.حَلّ لُغَات.اِسْتَسْقٰی.سَقٰی (یَسْقِیْ) سے باب اِستفعال کا ماضی کا صیغہ ہے اور اِسْتَسْقَی
Page 124
الرَّجُلُ مِنْ فُـلَانٍ اِسْتِسْقَاءًکے معنی ہیں طَلَبَ السَّقْيَ وَاِعْطَاءَ مَا یَشْرَبُہٗ یعنی کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے یہ خواہش کی کہ وہ اسے پینے کے لئے کچھ دے.(اقرب) قَوْمٌ.اَلْقَوْمُ: اَلْجَمَاعَۃُ مِنَ الرِّجَالِ خَاصَّۃً وَ قِیْلَ تَدْخُلُہُ النِّسَاءُ عَلٰی تَبْعِیَّۃٍٍ یعنی لفظ قوم مردوں کی جماعت کے لئے ہی بولتے ہیں لیکن بعض اہلِ زبان کا یہ خیال ہے کہ اگرچہ یہ لفظ مردوں کی جماعت پر ہی بولا جاتا ہے لیکن تاہم عورتیں بھی اس میں ضمنًاآ جاتی ہیں کیونکہ وہ بھی مختلف انسانی جماعتوں کا ایک حصہ ہوتی ہیں.(لسان میں لکھا ہے کہ لفظ قوم میں مرد اور عورت ہر دو آ جاتے ہیں لیکن جن لوگوں نے لفظ قوم کو مردوں کی جماعت کے لئے مخصوص کیا ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں آتا ہے.لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ (الحجرات:۱۲) اگر قوم میں عورتیں بھی داخل ہوتیں تو لفظ قوم کے ذکر کے بعد عورتوں کا ذکر نہ ہوتا جن لوگوں نے لفظ قومکو مردوں اور عورتوں ہر دو کی مشترکہ جماعت کے لئے بولے جانے کے حق میں کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کے ماننے والوں یا جن کی طرف وہ مبعوث ہوتا ہے اس کو قوم کہا گیا ہے اور اس میں مردوعورت ہر دو شامل ہوتے ہیں.نیز جب یہ کہا جائے قَوْمُ کُلِّ رَجُلٍ تو اس کے معنے ہوتے ہیں شِیْعَتُہٗ وَ عَشِیْرَتُہٗ کنبہ اور کنبے میں مرد و عورت ہر دو شامل ہوتے ہیں ).اقرب الموارد کا مصنّف کہتا ہے کہ مردوں کی جماعت کو قوم اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے وجودوں سے بڑے بڑے کام قیام پذیر ہوتے ہیں پھر لکھا ہے کہ لفظ قوم ہر دو طرح استعمال ہو جاتا ہے.مذکّر بھی اور مؤنث بھی.چنانچہ کہہ دیتے ہیں قَامَتِ الْقَوْمُ وَ قَامَ الْقَومُ.قَوْمٌ کی جمع اَقْوَامٌ.اَقَاوِمُ.اَقَاوِیْمُ.اور اَقَائِمُ.آتی ہے.(اقرب) قُلْنَا.قَالَ سے متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے اور معنے یہ ہیں کہ ہم نے کہا.ہم نے وحی کی.قَالَ ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر قَوْلٌ ہے.مفرداتِ راغب میں لکھا ہے کہ اَلْقَوْلُ یُسْتَعْمَلُ عَلٰی اَوْجُہٍ لفظ قَوْل کئی معانی کو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے.اَظْھَرُ ھَا اَنْ یَّکُوْنَ لِلْمُرَکَّبِ مِنَ الْحُرُوْفِ الْمُبْرَزِ بِالنُّطْقِ مُفْرَدًا کَانَ اَوْجُمْلَۃً (۱) زیادہ تر حروف سے مرکب مفہوم پر بولا جاتا ہے خواہ وہ مفرد ہو یا جملہ.اَلثَّانِیْ یُقَالُ لِلْمُتَصَوَّرِ فِی النَّفْسِ قَبْلَ الْاِبْرَازِ بِاللَّفْظِ قَوْلٌ (۲)نفس میں کسی سوچی ہوئی بات پر جو ابھی بول کر ظاہر نہ کی گئی ہو اس پر بھی قول کا لفظ استعمال کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں فِیْ نَفْسِیْ قَوْلٌ لَمْ اُظْھِرْہُ کہ میرے نفس میں ایک خیال ہے جس کو میںنے ظاہر نہیں کیا.اَلثَّالِثُ لِلْاِعْتِقَادِ (۳) کسی کے کوئی عقیدہ رکھنے کے مفہوم
Page 125
کو ظاہر کرنے پر بھی قول کا لفظ بولتے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں.فُـلَانٌ یَقُوْلُ بِقَوْلِ اَبِیْ حَنِیْفَۃَ کہ فلاں شخص امام ابوحنیفہؒ کا عقیدہ رکھتا ہے.اَلرَّابِعُ یُقَالُ لِلدَّلَا لَۃِ عَلَی الشَیْءِ (۴) اگر کسی چیز کی حالت کسی بات پردلالت کرے تو اس وقت بھی قَوْل کا لفظ استعمال کرتے ہیں چنانچہ اِمْتَـلَأَ الْحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِیْ میں قَالَ انہی معنوں میںاستعمال ہوا ہے یعنی جب حوض پانی سے بھر گیا تو اس نے کہا بس! بس! اب زیادہ پانی نہ ڈالو (اس کا مطلب یہ نہیں کہ حوض زبان سے بولا.بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حوض کی حالت بزبان حال یہ کہہ رہی تھی کہ وہ بھر گیا ہے اور اس میں مزید پانی کی گنجائش نہیں چنانچہ اس قسم کی مثالیں لغت کی کتب میں بکثرت ملتی ہیں.کہ کسی واقعہ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے قَالَ کا لفظ استعمال کر لیاجاتا ہے چنانچہ مندرجہ ذیل اشعار بھی اس امر کی مثالیں ہیں ؎ قَالَتْ لَہُ الْعَیْنَانِ سَمْعًا وَطَاعَۃً وَ حَدَرَتَا کَالدُّ رِّ لَمَّا یُثَـقَّبُ ( لسان) یعنی اسے دونوں آنکھوں نے کہا کہ تمہارا کہنا سر آنکھوں پر اور پھر وہ ایسے موتیوں کی طرح بہہ پڑیں جن میں ابھی چھید نہ ڈالا گیا ہو ؎ قَالَتْ لَہُ الطَّیْرُ تَقَدَّمْ رَاشِدًا اِنَّکَ لَا تَرْجِعُ اِلَّا حَامِدًا (لسان) یعنی پرندے نے اسے کہا کہ سیدھا راستہ اختیار کر کے آگے بڑھ اور تو واپس نہیں لوٹے گا مگر تعریف کرتا ہوا.ان اشعار میں قَوْل کے لفظ کی اضافت ایسی اشیاء کی طرف کی گئی ہے جو غیر ناطق ہیں یعنی پہلے شعر میں قول کا لفظ آنکھوں کی طرف منسوب کیا گیاہے اور مطلب یہ ہے کہ آنکھوں نے بزبانِ حال کہا اور دوسرے میں پرندے کی طرف.اور مطلب یہ ہے کہ پرندہ بزبانِ حال کہہ رہا تھا.تو گویا ان ہر دو اشعار میں قَالَ کے لفظ کو ایک واقعہ پر دلالت کرنے کےلئے استعمال کیا گیا ہے).اَلْخَامِسُ یُقَالُ لِلْعِنَایَۃِ الصَّادِقَۃِ بِالشَّیْ ءِ (۵) اگر کسی چیز کی طرف خاص توجہ ہو تو اس مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بھی قَالَ کا لفظ استعمال کرتے ہیں.اَلسَّادِسُ فِی الْاِ لْھَامِ (۶) قَوْلٌکا لفظ الہام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْنَا یٰذَالْقَرْنَیْنِکہ ہم نے ذوالقرنین کو الہام کرتے ہوئے کہا کہ اے ذوالقرنین! (مفردات) پس قَالَ کے معنے صرف یہ نہیں کہ انسان کسی کو مخاطب کرتے ہوئے منہ سے کوئی بات کہے بلکہ لفظ قَوْل مختلف معنوں میں استعمال
Page 126
ہوتا ہے اورہر مقام پر اس کے مناسب حال معنی ہوں گے.فَانْفَجَرَتْ.اِنْفَجَرَتْ اِنْفَجَرَ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اِنْفَجَرَ فَـجَرَ سے بابِ انفعال ہے.فَـجَر الْمَاءَ (یَفْجُرُ) کے معنے ہیں بَجَسَہٗ وَفَتَحَ لَہٗ طَرِیْقًا فَـجَرَیٰ پانی کو جاری کیا.پانی کو بہایا.پانی کے لئے راستہ کھول دیا اور وہ بہہ پڑا.اور فَـجَرَالْقَنَاۃَ کے معنے ہیں شَقَّھَا وَ قِیْلَ شَقًّا وَاسِعًا پانی کی نالی کو وسیع طور پر پھاڑ کر بنایا.اور جب اِنْفَجَرَالْمَاءُ کہیں تو معنے ہوں گے سَالَ وَجَرَیٰ.پانی بہہ پڑا (اقرب) پس اَ لْاِنْفِجَارُ کے معنی ہوں گے اَ لْاِنْشِقَاقُ.اَلتَّفَتُّحُ.پھوٹ پڑنا.بہہ پڑنا.اور اِنْفَجَرَتْ کے معنے ہوں گے.پھوٹ پڑے.بہہ پڑے.اُ نَاسٌ.اَ لْاُ نَاسُ.اَ لْاِنْسُ کی جمع ہے.اور اَ لْاِنْسُ کے معنے ہیں اَلْبَشَرُ آدمی اَوْغَیْرُ الْجِنِّ وَالْمَلَاکِ.جنوّں اور فرشتوں کے سوا آدم زاد (اقرب) اُنَاسٌ بعض وقت قبیلہ اور گروہ کے معنے میں بھی آ جاتا ہے.(تاج ) مَشْرَبَھُمْ.اَلْمَشْرَبُ کے معنے ہیں اَلْمَاءُ.پانی.اَلْوَجْہُ الَّذِیْ یُشْرَبُ مِنْہُ پانی پینے کی جگہ شَرِیْعَۃُ النَّھْرِ.دریا کا گھاٹ.مَشْرَبٌ کی جمع مَشَارِبُ آتی ہے.(اقرب) لَا تَعْثَوْا.عَثِیَ یَعْثٰی سے نہی مخاطب کا صیغہ ہے اور عَثِیَ کے معنے ہیں اَفْسَدَ اس نے فساد کیا بَالَغَ فِی الْفَسَادِ اَ وِالْکِبْرِ اَوِ الْکُفْرِ یعنی اس نے حدسے بڑھ کر فساد یاتکبر یا کفر کیا (اقرب) لسان میں لکھا ہے کہ عَثِیَ کے معنے ہیں اَفَسَدَ اَشَدَّ الْفَسَادِ سخت ترین فساد کیا اور اَلْعُثُوُّ کے معنی ہیں اَشَدُّ الْفَسَادِ.سخت ترین فساد (لسان) امام راغب کہتے اَلْعَیْثُ اَکْثَرُ مَا یُقَالُ فِی الْفَسَادِ الَّذِیْ یُدْرَکُ حِسًّا وَ الْعَثِيُّ فِیْمـَا یُدْرَکُ حُکْمًا کہ عَثِیٌّ کا لفظ عمومًا ایسے فساد کے لئے استعمال ہوتا ہے جو غیر محسوس ہو اور عَیْثٌ کا لفظ محسوس فساد کے لئے بولا جاتا ہے (مفردات) پس لَا تَعْثَوْا کے معنے ہوں گے (۱) سخت ترین فساد نہ کرو (۲) تم انتہائی طور پر فساد‘ تکبر اور کفر نہ کرو.مُفْسِدِیْنَ.اَفْسَدَ سے اسم فائل مُفْسِدٌ آتا ہے اور مُفْسِدُوْنَ اور مُفْسِدِیْنَ اس کی جمع ہیں اَفْسَدَ کے معنے ہیں ضِدُّ اَصْلَحَہٗ کسی چیز میں خرابی ڈال دی.اس میں فساد پیدا کر دیا اور جب اَفْسَدَ بَیْنَ الْقَوْمِ کہیں تو معنے ہوں گے لوگوں میں پھوٹ ڈال دی اور اَلْفَسَادُ کے معنے ہیں.جھگڑا.نقصان.خرابی.اَخْذُالْمَالِ ظُلْمًا ظلم سے کسی کا مال لینا نیز فساد کے ایک معنی قحط کے بھی کئے گئے ہیں.(اقرب) تفسیر.وَ اِذِ اسْتَسْقٰى الخ میں بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری کا ذکر یہاں ایک اور ناشکری بنی اسرائیل کی بیان کی گئی ہے.کہیں پانی کی دقّت ہوئی (معلوم ہوتا ہے یہ ایسا علاقہ تھا جہاں خدا تعالیٰ کی
Page 127
طرف سے بادل نازل نہیں کئے جاتے تھے.بادلوں کے علاقہ کو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے) موسیٰ علیہ السلام نے اﷲ تعالیٰ سے پانی کے لئے دعا کی اور انہیں حکم ہوا کہ فلاں پتھر کو اپنے سونٹے سے مارو.انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس پتھر میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے اور ہر ایک جماعت نے اپنے لئے ایک گھاٹ تجویز کر لی.پادری صاحبان کا آیت اِذِ اسْتَسْقٰى پر اعتراض کہ ایسا واقعہ بائبل میں مذکور نہیں پادری صاحبان اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ بائبل میں مذکور نہیں مگر جیسا کہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں بائبل میں کسی واقعہ کا بیان ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی اہم بات نہیں.بیشک ایک مؤرّخ مجبور ہے کہ وہ انہی واقعات کو بیان کرے جو بائبل میں یا دوسری تاریخوں میں بنی اسرائیل کے متعلق مذکور ہیں لیکن جو کلام اس بات کا مدّعی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے وہ اس بات پر مجبور نہیں ہے کہ وہ بائبل یا تاریخ کے حوالوں کو بیان کرے.جو باتیں بائبل اور تاریخ میں بیان ہوئی ہیں کیا ان کے سوا دنیا میں اور کوئی واقعہ نہیں ہوا اور کیا پھر ایسے واقعات کو بیان کرنا خدا تعالیٰ کے لئے ممنوع ہے.قرآن خدا کی کتاب ہے اور خدا تعالیٰ کے علم کو تاریخ دانوں کا علم نہیں پہنچ سکتا.قرآن کا مُنکر ہم سے اس بات کا مطالبہ تو کر سکتا ہے کہ ثابت کرو قرآن خدا کی کتاب ہے لیکن جب ہم ثابت کر دیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے تو اِس کے بعد قرآن کی گواہی ہر مؤرّخ کی گواہی سے اور ہر منسوخ یا ممسوخ کتاب کی گواہی سے یقیناً زیادہ معتبر سمجھی جائے گی مگر اس کے یہ بھی معنے نہیں کہ ہم قرآن کریم کے الفاظ کے وہ معنے کریں جو قرآن کریم کے رُو سے ناجائز ہوں یا خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ عقل کے خلاف ہوں یا لغت کے خلاف ہوں.بعض مفسرین کا اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى کی تفسیر میں غلطی کرنا اس آیت پر جہاں پادریوں نے یہ غلط اعتراض کیا ہے کہ چونکہ یہ واقعہ بائبل میں بیان نہیں اس لئے اسے درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا.وہاں ہمارے بعض مفسّروں نے بھی اس میں غلطی کی ہے چنانچہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک چھوٹا سا پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اُٹھائے پھر تے تھے اور جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ اس پتھر کو مار کر اس میں سے بارہ چشمے پھوڑ لیا کرتے تھے یہ معجزہ نہیں یہ تو ایک تمسخر ہے.جب خدا تعالیٰ ایک علاقہ میں بادل لایا تھا اور دوسرے علاقہ میں اُس نے ایک پتھر پر سونٹا مارنے کا حکم دیا تو یہ معجزہ بھی خدا تعالیٰ کے طبعی قانون کے مطابق ہی ہونا چاہیے اس آیت کے صرف اتنے معنے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر سونٹا مارنے کا حکم دیا گیا.اس سونٹے کے مارنے سے وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس میں سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے جن لوگوں کو پہاڑوں پر جانے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض جگہ پر پہاڑوں کی چوٹیوں کا برفوں کا پانی جو کہ زمین کی سطح کے نیچے بہہ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ سطح زمین کے اتنے قریب آ جاتا
Page 128
ہے کہ معمولی سوٹی مارنے سے ہی وہاں سے پانی نکل آتا ہے اور ایسے چشمے صرف پہاڑوں پر ہی نہیں پائے جاتے، بعض دفعہ بیابانوں میں بھی خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ بعض طبعی قانونوں کے ماتحت سطح زمین کے قریب پانی آئے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ عرب کے ریگستانوں میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے نخلستان اور چشمے پائے جاتے ہیں.اُن پانی کی جگہوں کو جغرافیہ والوں کی اصطلاح میں اوسِس (Oasis) کہتے ہیں.اِسی طرح کے کسی مقام کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اﷲ تعالیٰ نے الہام سے خبر دے دی.جہاں پانی سب سے زیادہ سطح زمین کے قریب تھا اس کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا.اﷲ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر کو توڑ دو.اس کے نیچے سے پانی نکل آئے گا چنانچہ اُنہوں نے پتھر توڑ دیا اور پانی نکل آیا.معجزہ نہ اس میں ہے کہ پتھر میں سے پانی نکلا.نہ اِس میں ہے کہ نئے سرے سے پانی پیدا کیا گیا.معجزہ اس امر میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہام کے ساتھ خبر دی کہ فلاں پتھر کے نیچے پانی موجود ہے پس نہ تو اس واقعہ کے انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے اور نہ قانونِ قدرت کے خلاف شکل دینے کی کوئی وجہ ہے.پانی اُس جگہ پر قانونِ قدرت کے مطابق موجود تھا مگر انسان نہیں جانتے تھے کہ اس جگہ پر پانی موجود ہے صرف خدا کو معلوم تھا کہ یہاں پانی موجود ہے اور اﷲ تعالیٰ نے اپنے بندے موسیٰ ؑ کو اس بات کا علم دیا اور موسیٰ ؑ کے پتھر توڑ دینے سے چشمے کا پانی جو پتھر کی وجہ سے بند تھا باہر کی طرف بہہ پڑا اور اﷲ تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ وہ پتھر جو معلوم ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی گہرائی کا تھا سونٹے کی ضرب سے بارہ جگہ سے ٹوٹا اور بارہ ہی اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے.پہاڑوں پر جانے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک ایک جگہ سے بعض دفعہ متعدد چشمے پھوٹتے ہیں.کشمیر میں ایک جگہ ککڑناگ ہے جو جہلم کے منبع سے کوئی پندرہ سولہ میل کے فاصلہ پر ہے اور اسلام آباد کے شہر کے اوپر آٹھ دس میل پر ہے اس جگہ پر مَیں نے خود ایک چند گز کی جگہ کے اندر سے بہت سے چشمے پھوٹے ہوئے دیکھے جن کی تعداد غالباً درجن سے زیادہ تھی.موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے بارہ چشموں کے پھوٹنے کی وجہ بارہ چشمے پھوڑنے کی غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے کئی قبائل تھے اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے.ہر ایک کے لئے الگ الگ پانی میسّر آ گیا یا ہو سکتا ہے کہ بارہ چشموں کا پھوٹنا ایک اتفاقی امر ہو اور بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کو مدّنظر رکھ کر ایسا نہ ہوا ہو.اﷲ تعالیٰ نے اِس کا ذکر محض اس لئے کر دیا کہ وافر پانی مل گیا اور بنی اسرائیل نے بغیر تکلیف کے پی لیا.ایک سیاح کی شہادت کہ حوُرب کی چٹان پر بارہ چشموں کا نشان ملتا تھا اس جگہ اس امر کا ذکر کر دینا
Page 129
بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سیل اپنے ترجمۂ قرآن کے نوٹوں میں لکھتا ہے کہ پندرھویں صدی کے ایک سیاحؔ نے شہادت دی ہے کہ حُورب کی ایک چٹان میں سے اُس وقت بارہ چشموں کا نشان ملتا تھا گو وہ سارے چلتے نہ تھے.(القرآن مصنّفہ سیل صفحہ۸.Al-Quran by Sale Page 8) اس شہادت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقہ میں بعض چٹانوں پر سے بارہ چشمے کسی زمانہ میں پھوٹا کرتے تھے.خروج باب ۱۷ میں حورب کی چٹان پر پانی کے لئے سونٹا مارنے کا حکم ثابت ہوتا ہے لیکن بارہ چشموں کا ذکر نہیں ملتا (آیت ۶) ہاں ایلیم ایک جگہ ہے جہاں بارہ چشموں کا ذکر ہے مگر وہاں سونٹا مارنے کا ذکر نہیں (خروج باب ۱۵ آیت ۲۷) لیکن جیسا کہ مَیں بتا چکا ہوں اِس بارہ میں بائبل کی شہادت کو زیادہ وقعت نہیں دی جا سکتی.بہر حال پندرھویں صدی کے ایک عیسائی سیّاح کی شہادت کہ حوُرب کی چٹان پر بھی بارہ چشمے پائے جاتے تھے کم سے کم عیسائی معترضین کا مونہہ بند کر دینے کے لئے کافی ہے.قَدْ عَلِمَ کُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَھُمْ سے مراد قَدْ عَلِمَ کُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَھُمْ سے یہ مراد نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ پانی الگ الگ قوم کے لئے مقرّر کیا گیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہر قوم نے اپنے لئے الگ جگہ مقرر کر لی یعنی پانی اتنی کثرت سے تھا اور اتنی متفرق جگہوں سے پھوٹا تھا کہ بنی اسرائیل کو پانی ملنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی اور آپس میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہوا بلکہ ہر قوم آسانی سے اپنے لئے الگ گھاٹ تجویز کر کے اس سے پانی پینے لگ گئی.کُلُّ اُنَاسٍ کے معنے ہر ایک قوم یا ہر ایک گروہ کے ہیں.ہر انسان اس کے معنے نہیں.كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ سے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اﷲ تعالیٰ تمہارے لئے ہر جگہ کھانے اور پینے کی چیزیں مہیّا کر رہا ہے.تم اس کے احسان کی قدر کرو، اس پر تو ّکل کرو اور اپنی نظر اسباب پر نہ رکھو.جتنے فساد دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں.کسی زمین یا کسی مکان یا کسی جانور یا کسی دھات کے متعلق انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے نہ ملی تو میرا نقصان ہو گا اور وہ اپنے بھائی سے لڑ پڑتا ہے اور فساد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.ہم نے اس وقت کے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں ان سب جھگڑوں سے آزاد کر دیا.نہ تمہیں کھانے کے لئے تلاش اور محنت کرنی پڑتی ہے، نہ تمہیں پانی کے لئے تلاش اور محنت کی ضرورت پیش آتی ہے پس جب ہم تمہاری سب ضروریات خود پورا کر رہے ہیں تو فساد کی کوئی وجہ نہیں.اب بھائی کو بھائی سے کیوں بغض ہو اور ہمسایہ ہمسایہ سے کیوں لڑے پس کم سے کم اِن ایّام میں تو تمہیں کوئی فساد نہیں کرنا چاہیے اور پھر ان ایاّم کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے تمہیں آئندہ بھی فساد نہیں کرنا چاہیے.
Page 130
عَثٰیکے معنے عَثٰی کے معنے جیسا کہ لغت میں بتائے جا چکے ہیں شدید فساد کے ہوتے ہیں.وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ کے معنے ہوئے زمین میں فساد کرتے ہوئے سخت فساد مت کرو.یہ عربی کا محاورہ ہے اور اس محاورہ کے رُو سے اس کے معنی یہ ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے فساد مت کرو.بعض دفعہ انسان سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جو موجب ِفساد ہوتی ہے مگر اس کے پیچھے فساد کی نیّت نہیں ہوتی.مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے مواقع سے بھی بچے لیکن کم سے کم اُسے ایسے کاموں سے تو ضرور بچناچاہیے جن کے متعلق اسے معلوم ہو کہ اس کا نتیجہ فساد ہو گا اور یہی مفہوم اس آیت کا ہے.چونکہ اردو زبان میں اس کا لفظی ترجمہ یوں بنتا ہے ’’ فساد کرتے ہوئے زمین میں سخت فساد نہ کرو.‘‘ اور یہ اردو ترجمہ بے معنی ساہو جاتا ہے اس لئے ہم نے عربی محاورہ کو مدِّنظر رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے ’’اور مفسد بن کر زمین میں خرابی نہ پیدا کرو.‘‘ وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کرسکیں گے اس لئے تو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لئے بعض ایسی چیزیں جنہیں زمین اگاتی ہے پیدا کر ے یعنی اس کی قِثَّآىِٕهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا١ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ سبزیاں،ککڑیاں، گیہوں، مسور اور پیاز.(اس پر اللہ نے )کہا کہ کیا تم اس چیز کی بجائے الَّذِيْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ١ؕ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ جو اعلیٰ ہے اس چیز کو لینا چاہتےہو جو ادنیٰ ہے.کسی شہر میں چلےجاؤ(وہاں) جوکچھ تم نے مَّا سَاَلْتُمْ١ؕ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ١ۗ وَ مانگا ہے تمہیں ضرور مل جائے گا( تب) انہیں ہمیشہ کے لئے ذلیل اور بے بس کر دیا (گیا )اور وہ اللہ کے
Page 131
بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ١ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ غضب کا مورد بن گئے.یہ اس وجہ سے( ہوا) کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ١ؕ ذٰلِكَ بِمَا اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے (اور) یہ( گناہ)ان کی نافرمانی کرنے اور حد سے بڑھے ہوئے ہونے عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَؒ۰۰۶۲ کے سبب سے (ان میں پیدا ہو گیا)تھا.حَلّ لُغَات.لَنْ نَصْبِرَ.صَبَرَ (یَصْبِرُ) سے مضارع منفی متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے اور صَبَرْتُ نَفْسِیْ عَلٰی کَذَا کے معنے ہیں حَبَسْتُہَا کہ مَیں نے فلاں بات پر ثابت قدمی دکھائی (اقرب) تاج العروس میں ہے کہ ’’ بَصَائِر‘‘کے مصنّف کہتے ہیں.صَبْرٌ کے لغوی معنے روکنے اور رُکنے کے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے صبر کیا تو اس کے معنے ہوتے ہیں حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الْجَزْعِ وَ حَبْسُ الِلّسَانِ عَنِ الشَّکْوٰی وَ حَبْسُ الْجَوَارِحِ عَنِ التَّشْوِیْشِ نفس پر گھبراہٹ پیدا ہونے کے وقت قابوپائے رکھنا.زبان کوشکویٰ کرنے سے روکے رکھنا اور دیگر اعضاء سے تشویش کا اظہار نہ ہونے دینا ( تاج ) صَبْر کے معنی ہیں تَرْکُ الشِّکْوٰی مِنْ اَلَمِ الْبَلْوٰی لِغَیْرِ اللّٰہِ لَا اِلَی اللّٰہِ کہ مصیبت کے دُکھ کا شکوہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کے پاس نہ کرنا فَاِذَا دَعَا اللّٰہَ الْعَبْدُ فِیْ کَشْفِ الضُّرِّ لَا یُقْدَحُ فِیْ صَبْرِہٖ اگر بندہ اپنی رفع مصیبت خدا تعالیٰ کے پاس فریاد کرے تو اس کے صبر پر اعتراض نہ کیا جائے.کُلّیات ابی البقاء میں لکھا ہے کہ اَلصَّبْرُ فِی الْمُصِیْبَۃِ کہ صبر مصیبت کے وقت ہوتا ہے وَصَبَرَ الرَّجُلُ عَلَی الْاَمْرِ نَقِیْضُ جَزِعَ اَیْ جَرُؤَ وَ شَجُعَ وَتَجَلَّدَ اور صبر جزع یعنی شکوہ کرنے اور گھبرانے کے مقابل کا لفظ ہے اور صبر کے معنے ہوتے ہیں دلیری دکھائی جرأت دکھائی ہمت دکھائی اور صَبَر عَنِ الشَّیْ ءِ کے معنے ہیں اَمْسَکَ عَنْہُ کسی چیز سے رُکا رہا.صَبَرَ الدَّابَۃَ حَبَسَہَا بِلَا عَلَفٍ اور جب صَبَرَ کا مفعول دَآبۃ کا لفظ ہو تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ جانور کو چارہ نہ دیا نیز کہتے ہیں صَبَرْتُ نَفْسِیْ عَلٰی کَذَا.حَبَسْتُھَا کہ میں نے فلاں بات پر ثابت قدمی دکھائی چنانچہ محاورہ ہے صَبَرْتُ عَلٰی مَا اَکْرَہُ وَ صَبَرْتُ عَمَّا اُحِبُّ یعنی جب صَبَرَ کا صلہ
Page 132
عَلٰی ہو تو اس کے معنے کسی امر پر ثابت قدم رہنے کے ہوتے ہیں اور جب اس کا صلہ عَنْ ہو تو اس کے معنے کسی چیز سے رُکنے یا کسی کو اس سے روک دینے کے ہوتے ہیں.(اقرب) پس صَبْرٌ کے معنے (۱) بدیوں سے رُکتے رہنا اور نیکیوں پر ثابت قدم رہنا.(۲) خدا تعالیٰ کے راستہ میں تکلیف پر جزع فزع نہ کرنا.پس لَنْ نَصْبِرَ کے معنے ہوں گے ہم ثابت قدمی نہیں دکھا سکیں گے.طَعَامٍ.اِسْمٌ لِمَا یُوْکَلُ کَا لشَّرَابِ لِمَا یُشْرَبُ عربی زبان میں ہر اس چیز کو جو خوراک کا کام دے، طعام کہتے ہیں جیسے ہر پینے کی چیز کو شَرَاب کہتے ہیں وَقَدْ غَلَبَ الطَّعَامُ عَلَی البُرِّ ِّ اور زیادہ تر طعام کا لفظ گندم پر بولا جاتا ہے.وَرُبَّمَا اُطْلِقَ عَلَی الْحُبُوْبِ کُلِّھَا اور کئی دفعہ جملہ اقسام کے غلّوں پر طعام کا لفظ بول دیتے ہیں.طَعَامٌ کی جمع اَطْعِمَۃٌ آتی ہے اور جمع الجمع اَطْعِمَاتٌ آتی ہے.(اقرب) بَقْلٌ.اَلْبَقْلُ: مَایَنْبُتُ فِیْ بِزْرِہٖ لَا فِیْ اَرُوْمَۃٍ ثَابِتَۃٍ.بقل ان سبزیوں کو کہتے ہیں جو اپنے بیجوں میں نشوونما پاتی ہیں اور خوراک حاصل کرنے کے لئے ان کی لمبی چوڑی جڑھیں نہیں ہوتیں.وَ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ کُلُّ مَا اخْضَرَّتْ بِہِ الْاَرْضُ ابن فارس کہتے ہیں کہ ایسا سبزہ جس سے زمین ہری بھری نظر آتی ہے، بقل کہلاتا ہے.وَالْفَرْقُ مَا بَیْنَ الْبَقْلِ وَ دِقِّ الشَّجَرِ اَنَّ الْبَقْلَ اِذَا رُعِیَ لَمْ یَبْقَ لَہٗ سَاقٌ وَ الشَّجَرُ تَبْقَ لَہٗ سُوْقٌ وَ اِنْ دَقَّتْ.اور بقل اور چھوٹے چھوٹے پودوں میں یہ فرق ہے کہ بقل کو جب جانور چر جائیں تو اس کی ٹہنی باقی نہیں رہتی لیکن پودوں کی ٹہنیاں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتی ہیں (تاج ) لسان میں ہے اَلْبَقْلُ مِنَ النَّبَاتِ مَا لَیْسَ بِشَجَرٍ دِقٍّ وَ لَاجِلٍکہ چھوٹے یا بڑے درختوں کے علاوہ جو نباتات اور سبزی ہوتی ہے اس کو بقل کہتے ہیں.(لسان العرب) قِثَّائِھَا.اَلْقِثَّاءُ نَوْعٌ مِنَ الْفَاکِھَۃِ یُشْبِہُ الْخِیَارَ تُسَمِّیْہِ عَوَامُنَابِالْمَقْتِیْ یعنی قِثَّاءٌ ایک پھل کا نام ہے جو کھیرے کی طرح ہوتا ہے عوام الناس اسے ککڑی کہتے ہیں.(اقرب) فُوْمِھَا.اَلْفُوْمُ لُغَۃٌ فِی الثُّوْمِ.ثُوم جسے اُردو میںلہسن کہتے ہیں اس کے مترادف لفظ عربی میں فُوم ہے اس کا مفرد فُوْمَۃٌ آتا ہے.نیز اَلْفُوْمُ کے معنی ہیں اَلْحِنْطَۃُ گندم.اَلْحِمَّصُچنے اَلْخُبْزُروٹی وَسَائِرُ الْحُبُوْبِ الَّتِیْ تُخْبَزُ تمام غلّے جن سے روٹی بناتے ہیں.السُّنْبُلَۃُ غلّہ کی بالی.(اقرب) أَتَسْتَبْدِلُوْنَ.تَسْتَبْدِ لُوْنَ اِسْتَبْدَ لَ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور اِسْتَبْدَ لَہٗ وَ اِسْتَبْدَ لَہٗ بِہٖ کے معنے ہیں ایک چیز کے بدلے دوسری چیز لے لی لیکن جس لفظ پر ب آئے وہ دی جاتی ہے اور جس پر ب نہ آئے وہ لی جاتی ہے (اقرب) پس اَتَسْتَبْدِ لُوْنَ الَّذِیْ ھُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ ھُوَ خَیْرٌ کے معنے ہوں گے کیا تم اچھی چیز
Page 133
دے کر ادنیٰ چیز لیتے ہو.اَدْنٰی.اَدْنٰی اسم تفضیل کا صیغہ ہے.بعض اسے دُنُوٌّ سے بناتے ہیں اور بعض دَنَاءَ ۃٌ سے.جو دَنَاءَ ۃٌ سے بناتے ہیں وہ اس کے معنے اَخَسُُّّ کے کرتے ہیں یعنی رذیل چیز اور جو اَدْنٰی کو دُنُوٌّ سے بناتے ہیں وہ اس کے معنے اَقْرَبُ کے کرتے ہیں یعنی زیادہ قریب.لیکن پھر اس کے معنے یہ کرتے ہیں اَقَلُّ قِیْمَۃً کم قیمت (لسان).مفردات راغب میں ہے.یُعَبَّرُبِا لْاَدْنٰی تَارَۃً عَنِ الْاَصْغَرِ فَیُقَا بَلُ بِا لْاَکْبَرِ کہ کبھی اَدْنٰی سے مراد سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے اس وقت اس کے مقابل پر’’ اَکْبَرُ‘‘کا لفظ بولا جاتا ہے.وَ تَارَۃً عَنِ الْاَرْذَلِ فَیُقَا بَلُ بِالْخَیْرِ اور کبھی اَدْنٰی سے مراد کسی ارذل (ردّی) چیز کے ہوتے ہیں.اس وقت اس کے مقابل خَیْر (یعنی بہتر چیز) کا لفظ بولا جاتا ہے.وَتَارَۃً عَنِ الْاَوَّلِ فَیُقَابَلُ بِالْاٰخِرِ اور کبھی ادنیٰ سے مراد ابتدائی ہوتا ہے اور اس وقت اس کے مقابل آخر (بعد کی) کا لفظ بولا جاتا ہے.وَ تَارَۃً عَنِ الْاَقْرَبِ فَیُقَا بَلُ با لْاَقْصٰی اور کبھی اَدْنٰی (اقرب)یعنی قریب ترین کے معنوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس وقت ادنیٰ کے مقابل اقصٰی یعنی دُور کی چیز کا لفظ بولا جاتا ہے.(مفردات) اِھْبِطُوْا.(ھَبَطَ یَھْبِطُ یَھْبُطُ تَھْبُطُ سے) امر جمع کا صیغہ ہے.اِھْبُطُوْا امر مخاطب جمع کا صیغہ ہے اور ھَبَطَہُ (یَھْبُطُ ھَبْطًا) مِنَ الْجَبَلِ کے معنے ہیں اَ نْزَلَہٗ اس کو پہاڑ سے اُتارا.ھَبَطَ بَلَدًا کَذَا: دَخَلَہٗ کسی شہر میں داخل ہوا (یہ متعدّی بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ ھَبَطَہٗ بَلَدًا کَذَا کے معنے ہوں گے اَدْخَلَہٗ اس کو فلاں شہر میں داخل کیا) ھَبَطَ السُّوْقَ:اَتَاھَا بازار میں آیا.ھَبَطَ فُـلَانٌ مِنَ الْجَبَلِ (یَھْبُطُ وَ یَھْبِطُ ھُبُوْطًا) نَزَلَ پہاڑ سے اُترا.ھَبَطَ الْوَادِیَ: نَزَلَہٗ وادی میں اُترا.ھَبَطَ مِنْ مَوْضِعٍ اِلٰی مَوْضِعٍ آخَرَ: اِنْتَقَل ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا (اقرب) پس اِھْبِطُوْاکے معنے ہوں گے(۱) اپنی جائے قیام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ قیام پذیر ہو جائو (۲) نکل جائو.مِصْرًا.اَلْمِصْرُ: اَلْحَاجِزُ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ دو چیزوں کے درمیان کی روک.اَلْحَدُّ بَیْنَ الْاَرْضَیْنِ خَاصَۃً وَقِیْلَ الْحَدُّفِیْ کُلِّ شَیْ ءٍ دو ملکوں کے درمیان کی حدّ اور بعض ہر ایک چیز کی حدّ کو مصر کہہ دیتے ہیں.اَلْکُوْرَۃُ اَیِ الْمَدِیْنَۃُ وَالصُّقَعُ اَوْکُلُّ کُوْرَۃٍ یُقْسَمُ فِیْہَاالْفَیْءُ وَ الصَّدَقَاتُ وہ جگہ جہاں کثرت سے مکانات اور محل ہوں یا وہ آبادی جہاں صدقات تقسیم کئے جائیں یعنی بڑا شہر.مصر.شہر مصر کو بھی کہا جاتا ہے.جسے آجکل قاہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے.نیز کبھی مصر کے معنوں میں وسعت دے لی جاتی ہے اور ہر شہر پر یہ لفظ
Page 134
اطلاق پاتا ہے.(اقرب) ضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّ لَّۃُ.ضَرَبَہٗ بِیَدِہٖ وَ بِالْعَصَا کے معنے ہیں اَصَا بَہٗ وَصَدَمَہٗ بِھَا اس کو سونٹے کے ذریعہ سے یا ہاتھ سے مارا (اقرب) اور جب ضَرَبَ عَلٰی یَدَیْہِ کہیں تو معنے ہوں گے.اَمْسَکَ اس کو خرچ کرنے سے روک دیا اور ضَرَبَ الْقَاضِیْ عَلٰی یَدِ فُـلَانٍ کے معنے ہیں.حَجَرَ عَلَیْہِ وَمَنَعَہُ التَّصَرُّفَ کہ قاضی نے کسی کو معاملات اور مال میں تصرّف کرنے سے روک دیا.ضَرَبَ عَلَیْھِمُ الْجِزْیَۃَ کے معنے ہیں وَضَعَہَا وَ اَوْجَبَھَا عَلَیْھِمْ وَ اَلْزَمَھُمْ بِھَا.ان پر ٹیکس لگا دیا.جزیہ کا ادا کرنا لازم اور واجب کر دیا (اقرب) ذَلَّ کے معنے ہیں ھَانَ ذلیل و حقیر ہو گیا (اقرب) اور ذِلَّۃٌ کے معنے حقارت والی حالت اور جب ضَرَبَ عَلَیْہِ الذِّلَّۃَ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں اَذَلَّہٗ اس کو ذلیل کر دیا (اقرب) امام راغب لکھتے ہیں کہ ضُرِبَ عَلَیْھِمُ الذِّلَّۃُ کے معنے ہیں اِلْتَحَفَتْہُمُ الذِّ لَّۃُ یعنی ذلت نے انہیں چاروں طرف سے لپیٹ لیا.(مفردات) اَلْـمَسْـکَـنَـۃُ.اَلْـفَـقْـرُ مفلسی اَلذُّ لُّ ذلّت و خواری.اَلضُّعْفُ کمزوری.(اقرب) بَاءُ وْ بِغَضَبٍ.بَاءُ وْ: بَاءَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور بَاءَ کے معنے ہیں رَجَعَ.لوٹا (اقرب)اور بَاءَ بِہٖ کے معنے ہیں اَرْجَعَہٗ یعنی اس کو لوٹا لیا.(اقرب) اَلْغَضَبُ.کے اصلی معنے ثَوَرَانُ دَمِ الْقَلْبِ اِرَادَۃَ الْاِنْتِقَامِ کے ہیں یعنی غضب جرم کی سزا دینے کے ارادہ پر دل میں خون کے جوش مارنے کو کہتے ہیں لیکن جب یہ لفظ اﷲ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنے صرف جُرم کی سزا دینے کے ہوتے ہیں.دوسری باتیں اس وقت مدّ نظر نہیں ہوتیں.( مفردات) قَالَ عَلَیْہِ السَّلَامُ اِتَّقُوا الْغَضَبَ فَاِنَّہٗ جَمْرَۃٌ تُوْقَدُ فِیْ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ اَلَمْ تَرَوْا اِلٰی اِنْتِفَاخِ اَوْدَاجِہٖ وَ حُمْرَۃِ عَیْنَیْہٖ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غضب سے بچو کیونکہ وہ ایک چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں سلگائی جاتی ہے پھر فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب کسی کو غضب آتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں.وَاِذَا وُصِفَ اللّٰہُ تَعَالٰی بِہٖ فَالْمُرَادُ اَ لْاِنْتِقَامُ دُوْنَ غَیْرِہٖ اورجب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی صرف جُرم کی سزا دینے کے ہوتے ہیں دوسری باتیں اس وقت مدنظر نہیں ہوتیں.(مفردات) لسان میں ہے بَاءَ بِذَنْبِہٖ کے معنے ہیں اِحْتَمَلَہٗ وَصَارَ الْمُذْنِبُ مَاْوَی الذَّنْبِ اس نے گناہ کا بوجھ اُٹھالیا اور گناہ گار گناہ کا مقام بن گیا یعنی گناہ اس سے چمٹ گیا.پھر لکھا ہے کہ نیز بَاءَ بِذَنْبِہٖ کے معنے ہیں.کَانَ
Page 135
عَلَیْہِ عَقُوْبَۃُ ذَنْبِہٖ کہ اس پر اس کے قصور اور جُرم کی سزا وارد ہوئی.(لسان) امام راغب بَاءُ وْ بِغَضَبٍ مِّنَ ﷲِ کے معنے کرتے ہوئے لکھتے ہیں.اَیْ حَلَّ مَبْوَأً وَمَعَہٗ غَضَبُ اللّٰہِ اَیْ عُقُوْبَتُہٗکہ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ﷲِ کے معنے ہیں وہ اپنی جائے رہائش پر اس طرح ٹھہرا کہ اس کے ساتھ اﷲ کا غضب تھا.وَبِغَضَبٍ فِیْ مَوْضِعِ حَالٍ اَیْ رَجَعَ وَجَاءَ وَحَالُہٗ اَنَّہٗ مَغْضُوْبٌ.یعنی بِغَضَبٍ پر با جو آئی ہے وہ حالت کے اظہار کے لئے آئی ہے یعنی بَاءَ بِغَضَبٍ کہیں گے تو اس کے معنے ہوں گے وہ لوٹا درآنحالیکہ وہ غضب کا مورد ہو رہا تھا.پھر لکھا ہے وَ اِسْتِعْمَالُ بَا تَنْبِیْھًا عَلٰی اَنَّ مَکَانَہُ الْمُوَافِقَ یَلْزَمُہٗ فِیْہِ غَضَبُ ﷲِ.فَکَیْفَ غَیْرُہٗ مِنَ الْاَمْکِنَۃِ اور بَاءَ فعل کے بعد لفظ بَا کا صلہ لانا ان معنوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے گھر میں ان پر غضب نازل ہو رہا ہے.اگر وہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ ہوں تو نہ معلوم ان کا کیا حال ہو.(مفردات) پس بَاءُ وْ بِغَضَبٍ کے ایک معنے ہوں گے.وہ غضب کا مورد بن گئے.ان کے گھروں میں غضب نے اپنا گھر بنا لیا.یَکْفُرُوْنَ.کَفَرَسے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور کَانُوْا یَکْفُرُوْنَ بِاٰیٰتِ ﷲِ کے معنے ہیں وہ اﷲ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے.کَفَرَ الرَّجُلُ (یَکْفُرُ کُفْرًا) کے معنے ہیں ضِدُّ اٰمَنَکسی چیز کا انکار کیا.کَفَرَ نِعْمَۃَ اللّٰہِ وَبِنِعْمَتِہٖ جَحَدَھَا وَ سَتَرَھَا.اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور نا شکری کی (اقرب) اَلْکُفْرُ فِی اللُّغَۃِ سَتْرُالشَّیْ ءِ.کفر کے لغوی معنے کسی چیز کو ڈھانپنے کے ہیں.وَکُفْرٌ بِنِعْمَۃٍ وَکُفْرَانُھَا سَتْرُ ھَا بِتَرْکِ اَدَاءِ الشُّکْرِ او رکفر انِ نعمت کے معنے ہیں نعمت کا شکر ادا نہ کیا.وَلَمَّا کَانَ الْکُفْرُاَنْ یَّقْتَضِیَ جُحُوْدَ النِّعْمَۃِ صَارَ یُسْتَعْمَلُ فِی الْجُحُوْدِ اور کفر انِ نعمت میں نعمت کا شکریہ ادا نہ کرنا ایک طرح پر اس نعمت کا انکار تھا اس لئے کفر کا لفظ صرف انکار کے معنے میں مستعمل ہونے لگا.وَالْکَافِرُ عَلَی الْاِطْـلَاقِ مُتَعارِفٌ فِیْمَنْ یَجْحَدُ الْوَحْدَ نِیَّۃَ اَوِ النُّبُوَّۃَ اَوِ الشَّرِیْعَۃَ اَوْ ثَـلَا ثَھَا اور کافرکا لفظ جب اکیلا استعمال ہو تو اس کے معروف معنے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا آنحضرتؐ کی نبوت اور شریعت یا ان تینوں کا منکر ہو (مفردات) پس کَفَرُوْا کے معنے ہوں گے جنہوں نے انکار کیا.کفر کیا.حق پوشی کی.یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یا آنحضرت صلعم کی نبوت کا یا شریعت کا یا ان تینوں کا انکار کیا.اٰیٰتٌ.اٰیٰتٌ اٰیَۃٌ کی جمع ہے اور اٰیَۃٌ کے معنے علامت، نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں نیز قرآن کریم کے ہر ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جُدا کر دیا گیا ہو اٰیَۃٌ کہتے ہیں.(تاج )
Page 136
یَقْتُلُوْنَ.قَتَلَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور قَتَلَ کے معنے حَلِّ لُغَات سورۂ ہذا ۵۵ میں مندرجہ ذیل لکھے جا چکے ہیں (۱) کسی کو قتل کر دیا (۲) کسی سے قطع تعلق کر لیا (۳) کسی کو ذلیل کر دیا (۴) کسی کے کام کو باطل کرنے کی کوشش کی.علاوہ ازیں کہتے ہیں ھُوَ قَاتِلُ الشَّتَوَاتِ اَیْ یُطْعِمُ فِیْھَا وَ یُدْفیئُ یعنی جب کسی کے متعلق قَاتِلُ الشَّتَوَاتِ کا فقرہ کہیں تو اس سے یہ مراد ہوگی کہ وہ غرباء کو سردیوں میں کپڑے اور کھانا کھلا کر سردی کے اثر سے بچاتا ہے(لسان) نیز کہتے ہیں قَتَلَہٗ اور مطلب ہوتا ہے اَصَابَ قَتَالَہٗ کہ اس کے جسم کو چھوا یعنی مارا (مفردات) پس يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ کے معنی ہوںگے (۱) انہوں نے نبیوں کو مارا(۲) ان سے بے تعلقی کا برتاؤ کیا (۳) ان کے کام کو باطل کرنے کی کوشش کی (۴) نبیوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کی.الْـحَقُّ.حَقَّہٗ (یَحُقُّ) حَقًّاکے معنی ہیں غَلَبَہٗ عَلَی الْحَقِّ اس پر حق میں غالب آیا.راستی میں غالب آیا.اور حَقَّ الْاَمْرَ کے معنے ہیں اَثْبَتَہٗ وَ اَوْجَبَہٗ کسی امر کو ثابت کیا اور اس کو لازم کیا.وَکَانَ عَلٰی یَقِیْنٍ مِنْہُ کسی معاملہ کے متعلق یقینی خبر معلوم کر لی اور جب حَقَّ الْخَبْرَ کہیں تو اس وقت معنے ہوں گے وَقَفَ عَلٰی حَقِیْقَتِہٖ خبر کی حقیقت کو معلوم کر لیا اور حَقَّ الْاَمْرُ کے معنے ہیں وَجَبَ وَ ثَبَتَ کوئی امر ثابت ہو گیا اور واجب ہو گیا.اَلْحَقُّ ضِدُّ الْبَاطِلِ جھوٹ کے خلاف چیز یعنی سچ.اَ لْاَمْرُ المَقْضِیُّ ہو کر رہنے والی بات.اَلْعَدْلُ انصاف.اَ لْمِلْکُ مالکیّت.اَ لْمَوْجُوْدُ ، اَلثَّابِتُ یعنی ثابت رہنے والی چیز.اَلْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ شک کے بعد یقین کا آنا.(اقرب) امام راغب کہتے ہیں کہ اَلْحَقُّ کا مفہوم کئی طرح ادا کیا جاتا ہے جن میں سے ایک یہ ہے.یُقَالُ فِی الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ الْوَاقِعِ بِحَسْبِ مایَجِبُ وَفِی الْوَقْتِ الَّذِیْ یَجِبُ کہ کسی فعل یا بات کا بامحل.مناسب حال اور باموقع کرنے کا نام اَلْحَقُّ ہے.(مفردات) عَصَوْا.عَصَـٰی سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور عَصَاہُ (یَعْصِیْہِ) کے معنے ہیں خَرَجَ عَنْ طَاعَتِہٖ وَ خَالَفَ اَمْرَہٗ وَ عَانَدَہٗ اس کی اطاعت سے نکل گیا اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کی دشمنی کی ٹھان لی (اقرب) پس عَصَوْا کے معنے ہوں گے انہوں نے نافرمانی کی.اطاعت سے نکل گئے.یَعْتَدُوْنَ.اِعْتَدَیٰ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِعْتَدَیٰ عَلَیْہِ کے معنے ہیں ظَلَمَہٗ اس پر ظلم کیا.(اقرب) اَ لْاِعْتِدَاءُ.مُجَاوَزَۃُ الْحَقِِّّ یعنی اپنے حق سے تجاوز کرنے کا نام اِعْتَدَاء ہے.(مفردات) لسان میں ہے اَ لْاِعْتِدَاءُ اور اَلتَّعَدِّیْ اور اَلْعُدْوَانُ کے معنے ہیں اَلظُّلْمُ ظلم اور جب اِعْتَدَیٰ فَـلَانٌ عَنِ الْحَقِّ یا اِعْتَدَیٰ فَوْقَ الْحَقِّ کہیں تو اس کے معنے ہوں گے جَاوَزَ عَنِ الْحَقِّ اِلَی الظُّلْمِ کہ حق سے تجاوز کرتے ہوئے
Page 137
ظلم کو اختیار کر لیا.(لسان) پس یَعْتَدُوْنَ کے معنے ہوں گے(۱) وہ حق سے تجاوز کرتے تھے (۲) وہ ظلم کرتے تھے.تفسیر.وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ میں بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری کا ذکر اس آیت میں بنی اسرائیل کی پھر ایک اور ناشکری کا ذکر کیا گیا ہے جو مَنّ وسَلْوٰی کے انعام کے متعلق معلوم ہوتی ہے.ایک لمبے عرصہ تک بنی اسرائیل کو مَنّ و سَلْوٰی ملتا رہا.کبھی کبھی درمیان میں شہروں میں جانے اور وہاں رہائش اختیار کرنے کا موقع بھی مِل جاتا تھا مگر معلوم ہوتا ہے وہ ایک ہی قسم کی غذا دیر تک کھانے کی برداشت نہ کر سکے گو حق یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی نہ تھی اس میں بھی تنوّع موجود تھا مگر بنی اسرائیل مصر میں رہ کر شہری زندگی کے عادی ہو چکے تھے وہ بھنی ہوئی اور تلی ہوئی اور دم پخت چیزوں کے شوقین تھے پس وہ جنگلی غذاؤں پر مطمئن نہ تھے اور ان جنگلی غذاؤں کے پیچھے جو حکمت تھی اس کی قدر نہ کرتے تھے آخر ایک دن تنگ آ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے.ہماری برداشت سے یہ بات بڑھ گئی ہے بیشک تجھ میں طاقت ہو گی کہ ایک قسم کے کھانے پر صبر کرے اور تجھے اس کے بدلنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہو گی مگر تو ہماری خاطر (یہ مفہوم اُدْعُ لَنَاکے الفاظ سے نکلتا ہے جس کے معنے ہیں خدا تعالیٰ سے ہماری خاطر دعا کر) اﷲ تعالیٰ سے دعا کر کہ وہ ہمارے لئے زمین کی ہر قسم کی ترکاریاں نکالے یعنی ہمیں کسی ایسی جگہ پر ٹِک کر رہنے کی اجازت دی جائے جہاں کھیتی باڑی ہو سکتی ہو اور ہر قسم کے غلّے اور دالیں اور ترکاریاں اور سبزیاں ہم کو میسر ہوں.اﷲ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان سے فرمایا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلہ میں ایک ادنیٰ چیز کو لینا چاہتے ہو.عربی کا محاورہ ہے کہتے ہیں اِسْتَبْدَ لَہٗ بِہٖ: اَخَذَہٗ مَکَانَہٗ یعنی جس پر حرف ب آتا ہے وہ چیز چھوڑی جاتی ہے اور جو بغیر ب کے مفعول ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے پس اَتَسْتَبْدِ لُوْنَ الَّذِیْ ھُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیْ ھُوَ خَیْرٌ کے معنے ہوں گے کہ خَیْر کو چھوڑ کر اَدْنٰی لینا چاہتے ہو.اب رہا یہ سوال کہ خَیر کیا ہے اور اَدْنٰی کیا ہے.بعضوں نے کہا ہے کہ خیر سے مراد گوشت ہے اور ادنیٰ سے مراد ترکاریاں ہیں لیکن یہ درست نہیں.ترکاریاں بھی خیر ہیں اور گوشت بھی خیر ہے.اور نہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کھانا مِلتا ہو تو دوسرا نہ کھاؤ.بسا اوقات انسان کا دل پلاؤ کو نہیں کرتا دال کو کرتا ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ کے عذاب یا اس کی ناراضگی کا موجب نہیں ہو سکتی.حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ اُن غذاؤں کا جو جنگل میں بغیر محنت کے ملتی ہیں اُن غذاؤں سے مقابلہ کیا گیا ہے جو شہروں میں محنت و مشقت کے بعد ملتی ہیں.بنی اسرائیل کو اﷲ تعالیٰ نے ان جنگلوں میں اس لئے رکھا تھا تا غلامی کا اثر دُور ہو جائے اور مصریوں کی صحبت میں جن گناہوں کی عادت انہیں
Page 138
پڑ گئی تھی ان کا ازالہ ہو جائے اسی طرح غیر قوموں سے مل کر اُن کے مشرکانہ جذبات بار بار نہ بھڑکتے رہیں.بلکہ موسیٰ ؑ کی صحبت میں مستقل طور پر رہ کر توحید کو وہ اپنے اندر جذب کر لیں.جنگل میں آخر وہی غذائیں مِل سکتی ہیں جو جنگل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ اﷲ تعالیٰ نے اُن کے لئے مہیّا کر دیں.سبزیاں، ترکاریاں اور تمدّنی طور پر پکائے ہوئے کھانے تو آبادیوں سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور وہیں میسّر آ سکتے ہیں.بنی اسرائیل کے مطالبہ سے بھی یہ مراد نہ تھی کہ اُن کو ککڑیاں اور ترکاریاں ملیں بلکہ اُن کا بھی یہ مطلب تھا کہ ہم کو آبادیوں میں رہنے کی اجازت دی جائے ہم اس بدوی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں اور اﷲ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ کیا تم اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنیٰ کو لینا چاہتے ہو تو اس سے بھی یہ مراد نہیں کہ ترنجبین یا شہد یا کھمبیوں یا بٹیروں کو چھوڑ کر تم گندم اور ترکاریوں کو کیوں لینا چاہتے ہو بلکہ اس سے بھی یہ مراد ہے کہ کیوں تم اس اچھی زندگی کو چھوڑ کر جو تمہیں حکومت اور آئندہ فاتحانہ زندگی بسر کرنے کے قابل بنا رہی ہے اس زندگی کو قبول کرنا چاہتے ہو جو تمہاری حیثیت کو معمولی زمینداروں کی حیثیت میں تبدیل کر دے گی.تمہارا ایسا مطالبہ یا تو اِس وجہ سے ہے کہ تم بالکل کم عقل ہو اور اُس زندگی کی قدر کو نہیں سمجھتے جو خدا تمہیں دینے والا ہے اور یا پھر تم کو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان نہیں.تم سمجھتے ہو موسیٰ ؑ یونہی جھوٹ بول رہا ہے.بادشاہت ہمیں کہاں ملنی ہے کیوں زمیندارے کی زندگی سے بھی محروم رہیں اور یہ دونوں باتیں چونکہ بے ایمانی اور دناء ت پر دلالت کرتی تھیں اس لئے اﷲ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور ان پر ناراضگی کا اظہار کیا.بنی اسرائیل کے ایک کھانے پر تسلی نہ پانے کا ذکر بائبل میں بنی اسرائیل کا ایک کھانے پر تسلّی نہ پانے کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے چنانچہ گنتی باب ۱۱ آیت ۵ میں لکھا ہے.’’ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مفت مصر میں کھاتے تھے اور وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنا اور وہ پیاز اور وہ لہسن.‘‘ اِھْبِطُوْا مِصْرًاسے مراد ملک مصر کا دارالخلافہ نہیں اِھْبِطُوْا مِصْرًا بعض مفسرّین نے ناواقفی سے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ مصر جو ملک مصر کا دارالخلافہ ہے اُس میں ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا اور عیسائی مصنّفین نے ان معنوں کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اس پر خوب بغلیں بجائی ہیں اور قرآن کریم کی ناواقفیت پر ہنسی اُڑائی ہے حالانکہ ناواقف مفسرّین کا یہ بیان بھی غلط ہے اور معترضین کا یہ اعتراض بھی درست نہیں.ملک مصر کا دارالخلافہ مصر تو غیر منصرف ہے یعنی اس پر تنوین نہیں آ سکتی چنانچہ قرآن کریم میں دیکھ لو اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.اُدْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ( یوسف :۱۰۰) اسی طرح فرماتا ہے.اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ(الزخرف :۵۲) لیکن اس آیت میں تو مِصْرًا
Page 139
فرمایا ہے نہ کہ مِصْرَ.اور جب منوّن مصر آئے تو اس کے معنے محض شہر کے ہوتے ہیں نہ کہ ملک مصر کے دارالخلافہ کے.اور ملک مصر کا دارالخلافہ مصر اس سے مراد نہیں ہوتا.پس یہ اعتراض عربی زبان سے ناواقفیّت کا ثبوت ہے.اﷲ تعالیٰ نے اس جگہ پر صرف یہ اجازت دی ہے کہ کسی شہر میں چلے جاؤ تمہیں وہاں یہ چیزیں مل جائیںگی.وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ اس میں یہ بتایا ہے کہ چونکہ انہوں نے زمیندار ے کو ترجیح دی اور بادشاہت کے رستوں کو اپنے لئے بند کرنا چاہا ،اس لئے اﷲ تعالیٰ نے اُن پر ذلّت اور مسکنت نازل فرما دی.خدا کی قدرت ہے گو پیشگوئیوں کے ماتحت اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکومت تو ملی لیکن ان کا خدا تعالیٰ کے وعدوں سے باربار منہ پھیرنا ان کے لئے کچھ ایسا وبالِ جان بن گیا کہ اب دو ہزار سال سے وہ بادشاہت سے محروم ہیں اور تجارت اور زمیندارہ کے سوا اُن کے ہاتھ میں کچھ نہیں.بَآءُوْ بِغَضَبٍکا مطلب وَ بَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ.بَآئَ کے معنے اوپر بتائے جا چکے ہیں یعنی اُٹھا لینا اور ایسی طرح اُٹھانا کہ وہ اُس چیز کا مستقل محل بن جائے.پس بَآئُ وْ بِغَضَبٍ مِّنَ ﷲِ کے معنے یہ ہوں گے کہ وہ خدا کے غضب کو لے کر اپنے شہروں میں اُترے.گویا اپنا وطن اور اپنا ٹھکانا جو سب سے زیادہ امن کی جگہ ہوتی ہے وہی ان کے لئے عذاب اور تکلیف کی جگہ بن گئی.یوں بھی آئندہ زمانہ کے واقعات نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کا وطن کنعان ہمیشہ مصائب کی آماجگاہ بنا رہا.ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ.اﷲ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان کی کمی نتیجہ تھا، نبیوں کے مقابلہ کا.جب انہوں نے نبیوں کا ادب نہ کیا تو رفتہ رفتہ اُس کلام کا ادب اور اس پر ایمان بھی جاتا رہا جو وہ لائے تھے اور نبیوں کا مقابلہ انہوں نے اس لئے کیا کہ وہ بدکار اور گنہ گار تھے.نبیوں نے ان کو ہدایت کی تعلیم دی جو انہیں ناپسند معلوم ہوئی اور انہوں نے ان کا مقابلہ شروع کر دیا.علّت و معلول کے اصل پر غور کرنے والے لوگ اِس بات سے لُطف اُٹھا سکتے ہیں کہ کس طرح قرآن کریم ہر ایک بدی یا نیکی کی جڑ اور پھر اُس کی جڑ بتاتا ہے تاکہ انسان کسی بدی سے بچنے کے لئے پہلے اس کی جڑ کو کاٹے تا ایسا نہ ہو کہ کچھ مدّت کے بعد وہ بدی پھر عود کر آئے.بنی اسرائیل کے نبیوں کو قتل کرنے کا مطلب يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ِّ اس کے یہ معنے نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے.قتل کے معنے اس جگہ قتل کے ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اُس وقت تک کسی نبی کو بنی اسرائیل نے قتل نہیں کیا تھا.لفظ قتل کا جان سے مارنے کے علاوہ اور کئی معانی پر اطلاق پانا قَتل کے معنے لغت میں علاوہ قتل
Page 140
کرنے کے یہ بھی ہیں اوّل قَتَلَہُ اللہُ اﷲ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی.(لسان) دوم.اُقْتُلُوْا فُـلَانًا.اس سے اعراض کرو.(لسان) سوم.فُـلَانٌ قَتَلَہٗ.مِنَ الْقَتَالِ.قَتَالٌ سے نکلا ہے جس کے معنے اَلْجِسْمُ کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ اَصَابَ قَتَالَہٗ اس کے جسم کو چھؤا یعنی مارا.(اقرب) چہارم.کہتے ہیں فُـلَانٌ قَاتِلُ الشَّتَوَاتِ (لسان ) فلاں شخص سردیوں کا قتل کرنے والا ہے یعنی غریبوں کو کپڑے دے کرسردی کا اثر دُور کرتا ہے.پانچویں کہتے ہیں قَتَلَہُ الْعِشْقُ.عشق نے اس کو مار ڈالا.یعنی اس کی زندگی خراب کر دی اور اس کو دُکھ میں ڈال دیا (لسان) پس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ نبیوں کو تلوار سے قتل کرتے تھے کیونکہ موسیٰ ؑکے زمانہ تک کسی نبی کو بنی اسرائیل نے قتل نہیں کیا تھا.پس اس جگہ پر قتل کرنے سے مراد یہ ہو گی کہ وہ نبیوں کو پیٹتے تھے یا ان سے بے تعلّقی کا اظہار کرتے تھے یا یہ کہ ان کے کام کو باطل کرنے کی کوشش کرتے تھے.قرآن شریف میں بھی قتل کا لفظ مار دینے کے سِوا اَور معنوں میں استعمال ہوا ہے چنانچہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے متعلق آتا ہے.اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ١ۙ وَّ يَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ١ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ.(آل عمران :۲۲ ) چونکہ یہ آیت رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے متعلق ہے اس لئے اس کے یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم پر حملے کرتے تھے یا قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے یا آپؐ کے کام میں روک ڈالتے تھے کیونکہ نہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو انہوں نے قتل کیا اور نہ وہ ایسا کر سکتے تھے.ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے.وَ قَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ١ۖۗ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ(المومن :۲۹) یعنی آل فرعون میں سے ایک ایسا شخص جو موسیٰ ؑپر ایمان لایا تھا لیکن اپنا ایمان چھپا کر رکھتا تھا اُس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے کہا.کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اﷲ میرا رب ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بڑے بڑے نشانات لایا ہے.ظاہر ہے کہ فرعون یا اس کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا.زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا.يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ کے معنے پس يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ کے معنے قتل کا ارادہ کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ اﷲ تعالیٰ کے نشانوں کا انکار کرتے تھے اور اﷲ کے نبیوں موسیٰ ؑاور ہارون ؑ کو قتل
Page 141
کرنے کا ارادہ کرتے یا اُن سے قطع تعلق کرتے یا اُن سے لڑتے جھگڑتے یا اُن کی تعلیم کے پھیلنے میں روک بنتے تھے اس وجہ سے وہ نیکی سے محروم ہوتے جاتے تھے اور گناہوں میں ترقی کرتے جاتے تھے اور یہ انبیاء کے مقابلہ کرنے کا گناہ ان سے اس لئے صادر ہوتا تھا کہ اُن کی طبیعتوں میں سے اعتدال کا مادہ جاتا رہا تھا.جو شیلی طبیعتیں تھیں اور ہر بات میں حدّ سے نکل جانے کے عادی تھے.جس کی طبیعت میں غصّہ اور جوش پیدا ہو جاتا ہے وہ بڑی سے بڑی نیکیوں سے محروم ہو جاتا اور بڑے سے بڑے گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے.اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ جو لوگ ایمان لائے ہیں.اور جو یہودی ہیں.نیز نصاریٰ اور صابی (ان میں سے )جو (فریق )بھی اللہ پر مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ اور آخرت کے دن پر (کامل )ایمان لایا ہے اور اس نے نیک عمل کئے ہیں یقیناً ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان عِنْدَ رَبِّهِمْ١۪ۚ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۰۰۶۳ کا( مناسب) اجر ہےاور انہیں نہ( تو مستقبل کے متعلق) کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ (ماضی پر) وہ غمگین ہوں گے.حَلّ لُغَات.اٰمَنُوْا: اٰمَنَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اٰمَنَـہٗ اِیْمَانًا کے معنی ہیںاَمَّنَہٗ: اس کو امن دیا اور جب اس کا صلہ حرف باء ہو یعنی اٰمَنَ بِہٖ کہیں تو معنے ہوںگے صَدَّقَہٗ وَوَثَّقَ بِہٖ.اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا اور جب اٰمَنَ کے بعد لام صلہ ہو یعنی اٰمَنَ لَـہٗ کہیں تو اس کے معنے ہوںگے خَضَعَ وَ انْقَادَ یعنی فرمانبرداری اختیار کی.مطیع ہو گیا اور کہنا مان لیا (اقرب) اَلْاِیْمَانُ: اَلتَّصْدِیْقُ.ایمان جو اٰمَنَ کا مصدر ہے اس کے معنے تصدیق کرنے کے ہیں.(اقرب) تاج العروس میں ہے.اَ لْاِیْمَانُ یَتَعَدَّی بِنَفْسِہٖ کَصَدَّقَ وَبِاللَّامِ بِـاِعْتبَارِ مَعْنَی الْاِذْعَانِ وَبِالْبَاءِ بِـاِعْتبَارِ مَعْنَی الْاِعْتِرَافِ اِشَارَۃً اِلَی اَنَّ التَّصْدِیْقَ لَایُعْتَبَرُ بِدُوْنِ اِعْتِرَافٍ.کہ لفظ ایمان کبھی بغیر صلہ کے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کا صلہ لام آتا ہے اور اس میں اذعان یعنی فرمانبرداری کے معنے ملحوظ ہوتے ہیں.اور جب باء کے صلہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس وقت اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ایمان کے معنے تصدیق کے ہیں اور تصدیق کے ساتھ اعتراف بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو اعتراف کے معنے
Page 142
میں استعمال کر لیتے ہیں.پس یُؤْمِنُوْنَ کے تین معنے ہوں گے (۱) تصدیق کرتے ہیں (۲) اعتراف کرتے ہیں (۳) پختہ یقین اور اعتماد رکھتے ہیں.امام راغب اِیْمَان کی تشریح کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں کہ:.’’ اَ لْاِیْمَانُ یُسْتَعْمَلُ تَارَۃً اِسْمًا لِّلشَّرِیْعَۃِ الَّتِیْ جَاءَ بِھَا مُحَمَّدٌ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ وَ یُوْصَفُ بِہٖ کُلُّ مَنْ دَخَلَ فِیْ شَرِیَعَتِہٖ مُقِرًّا بِاللّٰہِ وَ بِنُبُوَّتِہٖ‘‘.یعنی ایمان کبھی اُس شریعت کے لئے بطور نام استعمال کیا جاتا ہے جو حضرت محمد مصطفٰے صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آنحضرت صلعم کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے شریعت محمدیہ میں داخل ہو، ایمان کے ساتھ موصوف کرتے ہوئے مومن کہتے ہیں.(یعنی لفظ مومن بولنے سے فوراً ذہن میں اس شخص کا تصور آتا ہے جو آنحضرتؐ پر ایمان رکھنے والا ہو) ’’وَتَارَۃً یُسْتَعْمَلُ عَلٰی سَبِیْلِ الْمَدْحِ وَیُرَادُ بِہٖ اِذْعَانُ النَّفْسِ لِلْحَقِّ عَلٰی سَبِیْلِ التَّصْدِیْقِ وَ ذَالِکَ بِـاِجْتِمَاعِ ثَلٰـثَۃِ اَشْیَاءَ تَحْقِیْقٌ بِالْقَلْبِ وَ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِحَسْبِ ذٰلِکَ بِالْجَوَارِحِ ‘‘.نیز کبھی لفظِ ایمان بطور مدح استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تصدیق کے ساتھ ساتھ نفس نے حق کی پوری اطاعت بھی کر لی ہے اور حق کے پوری طرح تابع ہو جانے کا اظہار تین چیزوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے (۱) دل سے صداقت کو حق قرا ردینا (۲) زبان سے اس کا اقرار کرنا (۳) اعضاء سے اس کے مطابق عمل کر کے پوری طرح صداقت کے تابع ہو جانے کا اظہار کرنا.گویا امام راغب نے اسی شخص کو حقیقی مومن قرار دیا ہے جس کے اندر تینوں مذکورہ بالا باتیں پائی جائیں.اگر کسی میں ان میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں.اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تصریح فرما دی ہے کہ محض زبان سے اقرار یا صرف دل سے یقین کر لینا اور زبان سے اقرار نہ کرنا کوئی معنے نہیں رکھتا جب تک کہ یہ اکٹھے نہ ہوں چنانچہ فرمایا.قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا١ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ (الحجرات :۱۵) یعنی اعراب نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ یہ درست نہیں.کیونکہ انہو ںنے زبان سے تو کہہ دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے لیکن ان کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا اور چونکہ ایسے لوگ مومن نہیں ہوتے اس لئے ان کے ایمان لانے کا دعویٰ غلط ہے.ایک اور جگہ آل فرعون کی نسبت فرمایا.جَحَدُوْا بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَاۤ اَنْفُسُهُمْ (النمل :۱۵) کہ انہوں نے ظاہر میں اور عمل سے اللہ تعالیٰ کے نشانات کا انکار کر دیا.حالانکہ ان کے دل ان نشانوں کے سچے ہونے کا اقرار کر چکے تھے.الغرض ایمان صرف منہ سے کسی بات کے اقرار کر لینے یا دل سے کسی کے سچا ہونے کا یقین کر لینے کا نام نہیں بلکہ جب تک (۱) دل سے صداقت کو حق قرار نہ دیا
Page 143
جائے (۲) اور پھر زبان سے اس کا اقرار کرتے ہوئے (۳) اعضاء سے اس کے مطابق عمل کا اظہار نہ کیا جائے اس وقت تک مومن کہلانا درست نہیں.ھَادُوْا.ھَادَ (یَھُوْدُ ھَوْدًا ) سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ھَادَا الرَّجُلُ کے معنے ہیں تَابَ وَ رَجَعَ اِلَی الْحَقِّ ِّ اس نے توبہ کی اور حق کی طرف رجوع کیا.چنانچہ جب کوئی شخص غلطی کر کے اس سے توبہ کرتا ہے اور اﷲ کی طرف رجوع کرتا ہے اس وقت کہتے ہیں ھَادَ الْمُذْنِبُ اِلَی اللہِ کہ قصور وار نے اﷲ کی طرف رجوع کیا.نیز کہتے ہیں ھَادَالرَّجُلُ اور مطلب یہ ہوتا ہے دَخَلَ فِی الْیَھُوْدِیَّۃِ کہ فلاں شخص نے یہودی مذہب اختیار کر لیا جب ھَادَ فِی الْمَنْطِقِ کا فقرہ بولیں تو اس کے معنے ہوں گے اَدَّاہُ بِسَکُوْنٍ وَرِفْقٍ کہ اس نے نرمی سے کلام کیا.ھَادَ سے اسم فاعل ھَائِدٌ بنے گا.اور ھَائِدٌ کی جمع ھُوْدٌ ہو گی (اقرب) پس اَلَّذِیْنَ ھَادُوْا کے معنے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا.اَلنَّصَاریٰ.تُبَّعُ الْمَسِیْحِ یعنی مسیح علیہ السلام کے پیروؤں کو نصاریٰ کہتے ہیں.نَصَارٰی جمع ہے بعض نے اس کا مفرد نَصْرَانِیٌّ لکھا ہے.یعنی ناصرہ بستی کی طرف منسوب ہونے والا.بعض کا خیال ہے کہ نَصَارٰی نَصْرَانٌ کی جمع ہے ( یعنی نَصْرَان بستی کی طرف منسوب ہونے والا) اور بعض نے اس کو نَصْرِیٌّ کی جمع بتایا ہے یعنی نَصْرہ بستی کی طرف منسوب ہونے والا (اقرب) امام راغب کہتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ کے پیروؤں کا نام اس واسطے نصارٰی رکھا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ مَنْ اَنْصَارِیْ اِلَی ﷲِ کہ اﷲ کے کام میں میرا کون مددگار ہو گا تو انہوں نے جوابًا کہا نَحْنُ اَنْصَارُ ﷲِ یعنی ہم مدد کرنے کے لئے تیار ہیں.چونکہ وہ مدد کے لئے تیار ہو گئے اس لئے اُن کو نَصَارٰی کہا گیا (مفردات) لیکن یہ معنے درست نہیں.حق یہی ہے کہ نصرانی کا لفظ ناصرہ سے نکلا ہے دیکھو تفسیری نوٹ.اَلصَّابِئِیْنَ.اَلصَّابِئُوْنَ اور اَلصَّابِئِیْنَ صَابِیْ ءٌ کی جمع ہے جو صَبَأَ َٔ کا اسم فاعل ہے.کہتے ہیں صَبَأَ الرَّجُلُ صَبْأً اور مراد یہ ہوتی ہے خَرَجَ مِنْ دِیْنٍ اِلٰی دِیْنٍ اٰخَرَ کہ اس نے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا (اقرب) نیز لکھا ہے اَلصَّابِئُوْنَ قَوْمٌ یَعْبُدُوْنَ النُّجُوْمَ وَ قِیْلَ قَوْمٌ یَزْعُمُوْنَ اَنَّھُمْ عَلٰی دِیْنِ نُوْحٍ قِبْلَتُہُمْ مَھَبَّ الشَّمَالِ عِنْدَ مُنْتَصَفِ النَّھَارِکہ صَابِئُوْنَ ایک قوم ہے جو ستاروں کی پرستش کرتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ صَابِئُوْنَ وہ لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر چلتے ہیں اور ان کا قبلہ بادِشمال کے چلنے کے رُخ پر ہے.(اقرب)
Page 144
عَمِلَ صَالِحًا.صَالِحٌ کے معنے وہ عمل جو فساد سے پاک ہو اور بامصلحت اور مناسب حال ہو.صَلَحَ الشَّیْءُ کے معنے ہیں ضِدُّ فَسَدَ کوئی چیز فساد سے پاک ہو گئی نیز کہتے ہیں ھٰذَ ایَصْلُحُ لَکَ اَیْ مِنْ بَا بَتِکَ یعنی یہ تیرے مناسب حال ہے اور صَالَحَہٗ کے معنے ہیں وَافَقَہٗ اس سے موافقت کی.اَلصَّالِـحُ کے معنے ہیں ضِدُّ الْفَاسِدِ فساد سے پاک وَالصَّلَاحِیَۃُ حَالَۃٌ یَکُوْنَ بِھَا الشَّیْ ءُ صَالِحًا وہ حالت جس سے کوئی چیز مناسب و موزوں ہو جائے (اقرب) پس صَالِحَاتٌ کے معنے ہوں گے وہ اعمال جو فساد سے پاک اور بامصلحت اور مناسب حال ہوں.اَجْرُھُمْ.اَ لْاَجْرُ.اَلثَّوَابُ بدلہ (اقرب) اَ لْاَجْرُ وَ الْاُجْرَۃُ مَایَعُوْدُ مِنْ ثَوَابِ الْعَمَلِ دُنْیَوِیًّا کَانَ اَوْ اُخْرَوِیًّا جو کسی کام کا بدلہ ملتا ہے خواہ وہ دنیوی ہو یا اُخروی اُسے اَجْر کہتے ہیں.(مفردات) رَبِّـھِمْ.رَبٌّ کے معنی اِنْشَاءُ الشَّیْ ءِ حَالًا فَحَالًا اِلٰی حَدِّ التَّـمَامِ کے ہیں (مفردات امام راغب) یعنی کسی چیز کو پیدا کر کے تدریجی طور پر کمال تک پہنچانا.خالی تربیت کے معنی بھی یہ دیتا ہے.خصوصاً جبکہ انسان کی طرف منسوب ہو.مثلاً قرآن کریم میں ماں باپ کی نسبت آتا ہے.كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (بنی اسرائیل :۲۵) یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے اس وقت میری تربیت کی جبکہ میں چھوٹا تھا.ربّ کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں.(اقرب) اسی طرح سردار اور مُطَاع کے بھی (اقرب) جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسفؑ کا قول ہے اُذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ(یوسف:۴۳)اور مصلح کے بھی معنی ہیں (اقرب) ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے.لیکن بغیر اضافت کے مطلق ربّ کا لفظ کبھی غیر اللہ کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا.مثلاً رَبُّ الدَّارِ.گھر کا مالک یا رَبُّ الْفَرَسِ.گھوڑے کا مالک تو انسان کو کہہ سکتے ہیں مگرجب خالی یہ کہیں کہ ربّ نے یوں کہا ہے یا کیا ہے تو اس کے معنے صرف اللہ تعالیٰ کے ہوںگے (مفردات ) ربّ کے معنے مفسرین نے خالق کے بھی کئے ہیں.لَاخَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ھُمْ یَحْزَنُوْنَ.خَوْفٌ اور حُزْنٌ کے معنے مفصل طور پر حَلِّ لُغَات سورۂ بقرہ آیت نمبر ۳۹میں بتائے جا چکے ہیں.خَوْف اور حُزْن میں یہ فرق ہے کہ خوف آئندہ زمانے کے متعلق ہوتا ہے اور حُزْن کسی واقعہ گزشتہ کی بناء پر ہوتا ہے اسی لئے ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ انہیں نہ تو ( مستقبل کے متعلّق) کسی قسم کا خوف ہو گا اور نہ (ماضی پر) وہ غمگین ہوں گے.تفسیر.یہود کا نام یہود رکھے جانے کی وجہ ھَادُوْا ھَادَ جیسا کہ لغت میں بتایا جا چکا ہے یہودی
Page 145
ہونے کو کہتے ہیں گو حلِّ لُغات میں ھَادَکے اور معنے بھی بتائے جا چکے ہیں لیکن یہ توارد ہے کہ عبرانی کا ایک لفظ عربی کے ایک لفظ کے مشابہ ہو گیا ہے ان معنوں کو دیکھتے ہوئے یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ یہودی کو اس لئے یہودی کہتے ہیں کہ اس میں ھَادَ والے معنے پائے جاتے ہیں بلکہ عربی ھَادَ اور ہے اور یہ ھَادَ یَھُوْدُ جو یہودی قوم کے نام کو بتانے کے لئے ہے اور ہے.یہ لفظ درحقیقت اُس نام کا معرب ہے جو بنی اسرائیل کے لئے ہجرت بابل کے بعد خود یہود میں اور اِرد گرد کے لوگوں میں رائج ہو گیا تھا چنانچہ عبرانی میں اسے ’’ یَیْہُوْدی‘‘ کہتے ہیں اور ارمی زبان میں ’’یہودائی‘‘کہتے ہیں اور پُرانی بابلی زبان میں اسے’ ’یا اُودائی‘‘ کہتے ہیں اور یہ لفظ ’’یَہُوْدَا‘‘ سے بنا ہے جو اُس علاقہ کا نام جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل اور قبیلے کے لوگ حکومت کرتے رہے ہیں اور جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا( انسائیکلوپیڈیا ببلیکا وجوئش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ JEW) درحقیقت اس علاقہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل کا زور تھا جس کا عبرانی تلفظ ییہودا ہے اس لئے اُس علاقہ کا نام ہی ’’ییہودا‘‘ ہو گیا اور پھر اس علاقہ میں رہنے والوں کو’یہودی‘ نام مِل گیا.چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بغاوت ہو گئی تھی اس لئے بنو یہود ا اور بنو بن یا مین حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹوں کی اولاد تو اس علاقہ میں رہ گئی اور باقی دس قبائل نے شمال میں اپنی الگ حکومت قائم کر لی اور اُن لوگوں کے مذہب میں کچھ خرابیاں واقع ہو گئیں.نبیوں کی بعثت بھی زیادہ تر اسی علاقہ میں ہوتی رہی جس میں بنو یہودا رہتے تھے.پس آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے دو فرقوں میں امتیاز کرنے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ یروشلم کے علاقہ کے باشندوں کا مذہب صحیح ہے اور دوسروں کا غلط.یہودی کا لفظ ایک نئی اصطلاح بن گیا اور اس کے یہ معنی کئے جانے لگے کہ وہ جو موسوی شریعت کا سچا پابند ہے.اس یہودی کے لفظ کو عربوں نے اپنی زبان میں استعمال کیا اور چونکہ یہود کا لفظ عربی کے مضارع کے صیغہ سے مشابہ تھا انہوں نے اس سے ماضی کا صیغہ ھَادَ بنا لیا.مگر ایک مستقل لفظ ھَادَ بھی عربی میں ہے وہ لفظ یہودیوں یا ان کے قبیلوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ اس کے معنے بالکل اور ہیں جیسا کہ حلِّ لُغات میں بتائے جا چکے ہیں.پس ان معنوں کے رُو سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ ھَادَ کا جو لفظ ہے یہ عربی ہے بلکہ ھَادَ کا لفظ یہودی لفظ سے ماضی کا صیغہ بنایا گیا ہے اور یہودی کا لفظ یہود اسے بنا ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں’ ’ یہودا‘‘ کے علاقہ میں رہنے والا اور اس کے اصطلاحی معنے ہیںموسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا متّبع.
Page 146
قرآن مجید کا بنی اسرائیل اور یہود ہر دو الفاظ کو مختلف مفہوموں میں استعمال کرنا اور اہل یورپ کا غلط اعتراض تعجب ہے کہ قرآن کریم جہاں کہیں مذہب کی طرف اشارہ کرتا ہے وہاں یہودی لفظ کا استعمال کرتا ہے اور جہاں قوم کی طرف اشارہ کرتا ہے وہاں بنو اسرائیل کا لفظ استعمال کرتا ہے اور قرآن کریم پر عیسائی مصنّف یہ الزام دھرتے ہیں کہ وہ اسرائیلی تاریخ سے واقف نہیں.حالانکہ قرآن کریم نے اسرائیل اور یہود کے لفظ کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے جبکہ خود انجیل میں اِس لفظ کا غلط استعمال ہوا ہے اور اس کے معنے اسرائیلی نسل کے آدمیوں کے لئے گئے ہیں اور آج بھی یورپ کے لوگ اس لفظ کو غلط استعمال کرتے رہتے ہیں ( اس کے لئے دیکھو نوٹ ۴۱ سورۂ بقرہ زیر آیت يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ الخ) مسیحیوں کا نام نصاریٰ رکھے جانے کی وجہ نَصَارٰی.نَصْرَانِیٌّ کی جمع ہے اور اس کے معنے ہیں نَاصِرَہ سے تعلق رکھنے والے یہود اور ممالک عربیہ کے لوگ اس نام سے مسیحیوں کو یاد کرتے تھے.نَاصِرَہ جس سے یہ لفظ نکلا ہے جلیل کا ایک گاؤں تھا اور پُرانے زمانہ میں’مسیح کے اپنے ملک‘ کے نام سے مشہور تھا کیونکہ یوحنّا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لینے سے پہلے حضرت مسیح اپنے خاندان سمیت وہیں رہا کرتے تھے.( دیکھو متی باب۴ آیت ۱۳.مرقس باب ۱ آیت ۹.لوقاباب ۱ آیت ۲۶.یوحنّا باب ۱ آیت ۴۶.اعمال باب ۱۰ آیت ۳۸) اسی گاؤں کے نام کی وجہ سے ابتدائی یہودی مذہبی کتب میں حضرت مسیحؑ کے ماننے والوں کو نصرانی لکھا جاتا تھا ان سے عربوں نے اس کو اخذ کیا اور آج تک ان میں یہی نام مشہور ہے.مسیح محمدی کے اتباع کی مسیح ناصری کے اتباع سے ایک مشابہت ( خدا کی قدرت ہے کہ اس زمانہ میں امّتِ محمدیہ کے مسیح موعودؑ کے اَتباع کو بھی ان کے مخالف قادیانی کہتے ہیں یعنی امام کی جائے قیام کی طرف انہیں منسوب کرتے ہیں.یہ مشابہت بھی نہایت عجیب ہے) رومی لوگ بھی ابتدائی زمانہ سے مسیحی لوگوں کو نصرانی کہنے لگے تھے ( دیکھو اعمال باب ۲۴ آیت ۵) لیکن باوجود اس کے یہ عجیب بات ہے کہ ناصرہ جس کے نام پر مسیح علیہ السلام کے اَتباع نے نام پایا ایک لمبے عرصہ تک اس میں یہودی ہی بستے تھے.مسیحی صدیوں سال بعد جا کر اس میں بسے (انسائیکلو پیڈیا ببلیکا زیر لفظ Nazarath) متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح ؑ کے مجازی والد یوسف نجّار اس جگہ ایک خواب کی بناء پر جا کر رہتے تھے.لکھا ہے ’’ اور خواب میں آگاہی پا کر جلیل کی اطراف میں روانہ ہوا اور ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا جا کے رہا کہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا (متی ب ۲ آیت ۲۲،۲۳)لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بائبل میں کہیں بھی اس پیشگوئی کا ذکر نہیں.سو یا تو یہ الہام کسی قریب کے
Page 147
زمانہ کے صوفی یا ولی کا ہو گا یا کسی اعتراض سے بچنے کے لئے انجیل نویسوں نے اس قسم کی تعبیر نصرانی کے لفظ کی کر لی.وَﷲ اَعْلَمُ بِالصَّوَاب.اَلصَّابِئِیْنَ.صابی قوم کون تھی؟ صابی قوم اس وقت مفقود ہے گو بعض قومیں عراق میں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے متعلق شبہ کیا جاتا ہے کہ وہ صابی الاصل ہیں.گزشتہ زمانہ میں عیسائیوں کا ایک فرقہ جو علاقہ بابل میں رہتا تھا صابی کہلاتا تھا اور اُن کو الکزائٹس (Elkesaitas) بھی کہتے تھے.وہ مذہباً یوحنّا بپتسمہ دینے والے کے متّبعین کے ساتھ زیادہ ملتے تھے (انسائیکلو پیڈیا ببلیکا زیر لفظ Sabians) اسی طرح صابی بعض ستارہ پرست اقوام کو بھی کہتے ہیں جو عراق، عرب وغیرہ میں کسی وقت پائی جاتی تھیں اور حران اُن کا صدر مقام تھا ( انسا ئیکلو پیڈیا برٹینیکازیر لفظ Sabians ) درحقیقت یہ لوگ سباء کے رہنے والے تھے لیکن آہستہ آہستہ اُن کا نام صابی بجائے ’س‘ کے’ص‘ سے استعمال ہونے لگ گیا.یہ لوگ ستارہ پرست تھے اور ایک الہامی قانون کے ماننے والے تھے.تاریخ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ لوگ اپنے آپ کو صابی کہتے تھے یا لوگوں نے ان کا نام صابی رکھ دیا تھا.تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ مامون کے وقت میں بھی اس قبیلہ کے کچھ لوگ ابھی موجود تھے.کیونکہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مامون نے رومی حکومت پر حملہ کرتے وقت اپنے رستہ میں اُن لوگوں کو دیکھا.اُن کے لمبے لمبے بالوں اور عجیب قسم کے لباس اور غیر معروف مذہبی رسوم کو دیکھ کر اُس نے حکم دیا کہ یا تو تم اپنے آپ کو کسی اہلِ کتاب مذہب سے وابستہ کر لو ورنہ میں تم کو قتل کر دُوںگا.انہوں نے مسلمان فقہا سے مشور ہ کیا اور ان کے مشورہ کے مطابق اپنا نام صابی رکھ لیا ( انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Sabians) میرے نزدیک یہ بات کہ انہوں نے بعد میں اپنا نام صابی رکھا غلط ہے.ممکن ہے کہ کوئی اُن کا چھوٹا سا قبیلہ الگ پڑا ہو اور وہ اپنا نام بھی بھُول گئے ہوں پھر انہوں نے مسلمان علماء کے مشورہ سے اپنا نام صابی بتایا ہو.کیونکہ اسلامی تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ حرّان کے لوگوں کا تعلق مامون کے زمانہ سے بہت پہلے اسلامی حکومت سے قائم ہو چکا تھا.صابی کے معنے اہل کتاب کے یہ کہ قرآن شریف میں صابی کے لفظ سے کون صابی مراد ہیں تعیین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا لیکن میرے نزدیک چونکہ صابی کا نام کئی اہلِ کتاب قومیں اپنی طرف منسوب کرتی تھیں عربی زبان میں صابی کے معنے اہل کتاب کے ہو گئے.یہود اور نصاریٰ کو تو وہ جانتے تھے اس لئے اُنہیں تو وہ خاص نام سے یاد کر لیتے تھے.ان کے سوا باقی تمام قومیں جنکی نسبت عرب سمجھتے تھے کہ یہ الہامی کتاب کے قائل ہیں انہیں وہ صابی کے نام سے یاد کر لیتے تھے پس گوصابی کا نام کسی وجہ سے کسی ایک نے یا دوسری وجہ سے بعض اور قبائل نے اپنے لئے
Page 148
استعمال کیا تھا لیکن عربوں کے نزدیک اس کے معنے ہر ایسی قوم کے تھے جو اہلِ کتا ب ہو اور یہودیوں اور نصاریٰ کے علاوہ ہو چنانچہ جب اسلام نیا نیا نکلا تو جب تک عرب کے لوگ اسلام کے نام اور اسلام کے مذہب سے مانوس نہیں ہوئے مسلمانوں کو بھی وہ صابی کہا کرتے تھے.جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو کہتے صَبَأَ فُـلَانٌ فلاں شخص صابی ہو گیا.میرے نزدیک کوئی حرج نہیں کہ ہم قرآنِ شریف میں بھی اس لفظ کے یہی معنی سمجھیں یعنی قرآنِ شریف نے بھی عربی محاورہ کے مطابق صابی سے مراد اہلِ کتاب کے لئے ہوں اور اس آیت سے مراد یہ ہو کہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اور کسی الہامی کتاب کی طرف منسوب ہونے والا ہو ہر ایک قوم کے متعلق اﷲ تعالیٰ کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ اگر وہ اﷲ اور یوم آخر پر سچا ایمان لائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ کبھی تباہ نہیں ہوں گے.آیت اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ ھَادُوْا...الخ کا گزشتہ آیات سے تعلق جیسا کہ اوپر کی آیات کی تفسیر سے ظاہر ہے چوتھے رکوع سے یہ مضمون پیش کیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی نبوّت نئی نہیں بلکہ نبوّت کا سلسلہ قدیم سے چلا آیا ہے چنانچہ پہلا انسان کامل بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا تھا.اور پھر پانچویں رکوع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ آدم پر ہی ختم نہیں ہو گیا بلکہ محمدرسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہ ٖوسلم کے قریب ترین زمانہ تک اﷲ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں چنانچہ عرب کے جوار میں رہنے والی اسرائیلی قوم میں ایک لمبا سلسلہ انبیاء کا چلا جس کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پڑی.اسی ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ خبر دی گئی تھی کہ ان کے دونوں لڑکوں اسماعیلؑ اور اسحاقؑ کے ذریعہ سے روحانیت کے عظیم الشاّن سلسلے چلیں گے.پس جبکہ نبوّت کا سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے شروع کیا گیا اور جاری رکھا گیا اور سابق انبیاء کی پیشگوئیوں نے بنو اسمٰعیل میں آنے والے ایک عظیم الشاّن نبی کی خبر دے رکھی ہے تو پھر ایک مدعیٔ نبوّت کے دعوے پر استعجاب کیوں ہو.دوسرا مضمون چوتھے رکوع سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی کے زمانہ میں اُس کی مخالفت کی گئی.آدم علیہ السلام پر بھی اعتراض ہوئے چنانچہ شیطان اور اُس کی ذرّیت نے خوب بڑھ بڑھ کر اعتراض کئے.فرشتوں نے گو اعتراض نہیں کیا مگر اُس کی پیدائش پر تعجب اور حیرت کا اظہار ضرور کیا.پھر اس کے بعد نبی پر نبی آیا اور یہ سبق دُہرایا گیا مگر اسلام کے قریب ترین رُوحانی سلسلہ کے نبیوں پر پھر اسی طرح اعتراضات ہوئے جیسے پہلے نبیوں پر اعتراضات ہوئے تھے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان اعتراضوں سے نہ بچے.پھر محمدرسول اﷲ صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کا انکار محض اس وجہ سے کہ اُن کی بعض باتوں پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکر درست ہو سکتا ہے.
Page 149
تیسرا سلسلۂ مضمون ان رکوعوں میں یہ جاری ہے کہ اﷲ تعالیٰ جب کسی قوم کو چنتا ہے تو اپنے فضل کو کمال تک پہنچا دیتا ہے لیکن جب وہ قوم ناشکری میں بڑھ جاتی ہے تو وہ فضل کسی دوسری قوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے.آدم ؑکی وسیع اولاد میں سے منتقل ہوتے ہوتے فضل الٰہی بنی اسرائیل میں آیا.اب بنی اسرائیل کی متواتر اور ایک لمبے عرصہ تک کی مسلسل ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے وہ فضل ایک دوسرے خاندان کی طرف منتقل ہوا ہے.بنی اسرائیل کو اب غصّہ کیوں آتا ہے اور مکّہ کے لوگ ناراض کیوں ہیں.نہ بنی اسرائیل کی خفگی کی کوئی وجہ ہے کہ انہوں نے خود دھکے دے دے کر خدا تعالیٰ کے فضل کو اپنے گھر سے نکالا اور نہ مکّہ والوں کے لئے شور مچانے کی کوئی وجہ ہے کہ اُن کے تاریک گھروں میں خدا تعالیٰ کے نور کا دیا جلایا جا رہا ہے.اُن کے افسردہ دلوں پر خدا تعالیٰ کی رحمت کی بارش نازل کی جا رہی ہے.اُن کے لئے تو خوش ہونے کا مقام ہے نہ کہ رنجیدہ ہونے کا.یہ تین سلسلۂ مضامین چوتھے رکوع سے شروع ہو کر اس جگہ تک آ رہے ہیں اور کچھ دُور تک آگے بھی جائیں گے چنانچہ اِس آیت سے اگلی آیت میں پھر وہی مضمون جاری ہوجائے گا لیکن اِس سلسلہ مضمون میں یہ آیت جس پر نوٹ لکھا جا رہا ہے بظاہر بے جوڑ سی معلوم ہوتی ہے.کہاں یہودیوں کا ذکر اور وہ بھی پرانے زمانے کے یہودیوں کا.پھر اس آیت کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ہی ذکر ہے درمیان میں یہ آیت کیسی آ گئی کہ جس میں مسلمانوں یا عام مومنوں کا بھی اور نصاریٰ کا بھی اور صابئین کا بھی ذکر ہے.اِس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں یہود کے اوپر مستقل طور پر غضب الٰہی نازل ہونے کا ذکر تھا اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ انبیاء کا مقابلہ کرتے رہے ہیں.یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا مضمون ہے کہ انسانی فطرت اس جگہ پر اپنی مشکلات کا حل کر دیئے بغیر آگے جانے دینا پسند نہیں کرتی.جس وقت انسان اِس مضمون کو پڑھتا ہے کہ ایک قوم پر خدا تعالیٰ کا فضل نازل ہوا اور فضل پر فضل نازل ہوا مگر اس نے نافرمانی پر نافرمانی کی اور نبیوں کا مقابلہ کیا تو اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے اس خطرناک حالت سے مَیں بچ سکتا ہوں.اس فطری سوال کا جو ضمنی طور پر اِس دل دہلا دینے والے مضمون کے موقع پر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس آیت میں جواب دے دیا گیا ہے.فرماتا ہے.یقیناً وہ لوگ جو ایمان کے مدعی ہیں خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا صابی ہیں جو بھی اﷲ پر اور یوم آخر پر ایمان لائیں اور مناسب حال عمل کریں ان کو ان کے رب کی طرف سے اجر ملتا ہے یعنی جو چیز انسان کے امن کو دوام بخشتی ہے وہ اﷲ تعالیٰ اور یومِ آخر پر ایمان اور عمل صالح ہے.یہ مت سمجھو کہ باوجود ایمان کے انسان ٹھوکریں کھاتا ہے.جب حقیقی ایمان نصیب ہو تو اس وقت انسان ٹھوکریں نہیں کھاتا.بنی اسرائیل
Page 150
نے اگر ٹھوکریں کھائیں تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ایمان کے ہوتے ہوئے وہ ٹھوکریںکھاتے تھے بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ایمان میں کمزوری تھی ورنہ جو شخص خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاتا ہے اور بعث بعد الموت پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مناسبِ حال عمل کرتا ہے وہ کبھی خدا تعالیٰ کے غضب کا مستحق نہیں ہوتا.پس اگر یہودیوں کو ٹھوکر لگی، اگر اُن کے بعد نصاریٰ کو ٹھوکر لگی اور اگرا ن کی ہمسایہ قوم صابئین کو ٹھوکر لگی تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ یا تو اُن کو اﷲتعالیٰ پر ایمان نہیں تھا یا یوم آخر پر ایمان نہیں تھا یا مناسبِ حال عمل اُن کے نہیں تھے چنانچہ دیکھ لو یہود کو اﷲ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں تھا تبھی تو انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا.اسی طرح یومِ آخر پر ایمان نہیں تھا تبھی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے چُن چُن کر یومِ آخر کے متعلق حوالے نکال پھینکے.یہی حال نصاریٰ کا ہے.نصاریٰ کو بھی اﷲ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا.اگر ایمان ہوتا تو وہ خدا تعالیٰ کے ایک بندے کو اس کا بیٹا کیوں بنا دیتے اور عمل صالح کا تو کوئی سوال ہی نہیں کیونکہ کفّارہ نے عمل کی ضرورت کو باطل کر دیا ہے.پس فرماتا ہے.یہودیوں کی اِس متزلزل حالت کو دیکھ کر اور اُن کے بارہ میں خدا تعالیٰ کے غضب کی پیشگوئیوں کو پڑھ کر گھبراؤ نہیں اور یہ نہ سمجھو کہ جب یہود جیسی قوم جس میں اس قدر اﷲ تعالیٰ کے نبی آئے اُس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تو اور کسی شخص کو اپنے رُوحانی انجام پر کس طرح اطمینان ہو سکتا ہے کیونکہ روحانی انجام کی درستی یقیناً ہو سکتی ہے.تم اﷲ اور یومِ آخر پر ایمان درست کرو اور عمل صالح کرو.پھر کوئی چیز تم کو جادہ ٔاعتدال سے پھرا نہیں سکتی.پھر کوئی چیز تم کو خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی.نہ ایسے شخصوں کے لئے سابق کا کوئی غم رہتا ہے اور نہ آئندہ کے لئے کوئی ڈر رہتا ہے.اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا میں تمام اقوام عالم سے خطاب یاد رہے کہ اِس آیت میں اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا میں تمام اقوامِ عالم کا ذکر ہے اور وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ میں زور دینے کے لئے خصوصیّت سے یہودیوں ، نصرانیوں اور صابیوں کا الگ ذکر کر دیا گیا ہے.گویا تفصیلی طور پر اس آیت کے معنے یوں ہو سکتے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ جو اﷲ تعالیٰ پر ایمان لائے.خاص طور پر ہم اس جگہ نام لے کر ذکر کر دیتے ہیں.یہودیوں ،نصرانیوں اور صابیوں کا کہ خواہ یہ ہوں یا کوئی اور قوم ہو، جو لوگ بھی اﷲ پر اور یومِ آخر پر ایمان لائیں اور مناسبِ حال عمل کریں انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا اور نہ اُنہیں آئندہ کا کوئی خوف ہو گا اور نہ گزشتہ باتوں پر کوئی غم ہو گا.اِن معنوں کی رُو سے اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے مراد مسلمان نہیں سمجھے جائیں گے بلکہ دنیا کی ہر قوم کے لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں، زرتشتی ہوں، یونانی ہوں، کنفیوشس مذہب والے ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، ساری ہی وہ قومیں جن کو دعویٔ ایمان ہے اس میں شامل ہیں اور اٰمَنُوْا کے اجمالی معنوں کی
Page 151
تشریح کرنے کے لئے الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى وَ الصّٰبِـِٕيْنَ کہہ کر تین ایسی مثالیں دے دی گئی ہیں جو عرب کے اِردگِرد رہنے والے مذاہب کی ہیں اور اس آیت سے اُس مایوسی کو دُور کیا گیا ہے جو گذشتہ آیات میں یہودیوں کے حالات کو پڑھ کر ایک مومن کے دل میں پیدا ہو سکتی تھی اور بتایا ہے کہ ایمان کا رستہ ایسا مخدوش نہیں جیسا کہ یہودیوں کی حالت سے ظاہر ہوتا ہے.انہوں نے خود اپنی حالت مخدوش بنا لی ورنہ روحانی رستہ تو بالکل کُھلا اور صاف ہے.اﷲ پر انسان ایمان لے آئے.یومِ آخر پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق عمل کرے ساری مشکلیں آپ ہی دُور ہو جاتی ہیں.سارے مسائل آپ ہی حل ہو جاتے ہیں.نہ نبیوں کے پہچاننے میں کوئی دقّت رہتی ہے، نہ دوسرے مسائل روحانیہ کی سچائی کے سمجھنے میں کوئی مشکل رہ جاتی ہے، نہ اخلاقی مسائل کی اُلجھنیں باقی رہتی ہیں، نہ عبادات کے ادا کرنے میں کوئی تکان پیدا ہوتی ہے اور نہ حقوق العباد کے ادا کرنے میں کوئی بوجھ محسوس ہوتا ہے.قرآن کریم کا یہ ایک کمال ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا مضمون ہو جس سے مایوسی پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو وہ دوسرا پہلو امید کا بھی ساتھ ہی پیش کر دیتا ہے اور جہاں کہیں امیداور خوشی کا مضمون ایسا زور دار ہو کہ اس سے غفلت اور سُستی پیدا ہونے کا احتمال ہو جائے تو وہ خوفِ خدا اور خشیت کا مضمون بھی مناسب طریقہ سے اس جگہ پر بیان کر دیتا ہے تاکہ ایمان کی حالت وسط میں رہے اور مسلم کا دل کسی ایک کیفیّت کی طرف منتقل ہو کر جادۂ اعتدال سے ہٹ نہ جائے.دوسری کتابوں کا یہ حال نہیں وہاں محبت کا ذکر ہے تو محبت کا ذکر ہی ہوتا چلا جاتا ہے یہانتک کہ دل میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے.عذاب الٰہی کا ذکر ہو تو عذاب الٰہی پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے.انجیل اور تورات اور دوسری تمام مذہبی کتابوں میں اِس توازن کو مدّنظر نہیں رکھا گیا صرف اور صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اس توازن کو مدِّنظر رکھتی اور ایسی حالت پیدا ہونے نہیں دیتی جو نامناسب امیدوں یاخطرناک مایوسیوں کی طرف انسان کو لے جائے.اِس آیت کا تعلق پہلی آیات سے ایک اور رنگ میں بھی پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ چونکہ گذشتہ آیات میں بار بار بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانیاں یاد دلائی گئی تھیں.شریف الطبع اور خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والے بنی اسرائیل ان واقعات کو یکجائی طور پر دیکھ کر یقیناً متأثر ہو سکتے تھے اور ڈر ہو سکتا تھا کہ وہ مایوس ہو جائیں اور سمجھیں کہ ہماری قوم کے لئے تو اب بخشش کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا.اس لئے اس آیت میں اس مایوسی کی حالت کو دُور کر دیا گیا اور اﷲ تعالیٰ نے بتایا کہ آج اسلام کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے پھر رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں.خواہ مسلمان کہلانے والے لوگ ہوں، خواہ یہودی، عیسائی یا اَور کسی کتاب کو ماننے والے ہوں اگر وہ آج بھی
Page 152
اسلامی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو درست کریں اور مناسبِ حال اعمال بجا لائیں تو اُن کی روحانی ترقّیات کے سامان پھر پیدا ہو سکتے ہیں.وہ پھر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں.وہ پھر اﷲ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہو سکتے ہیں.ان کی قوم کی گذشتہ بداعمالیاں اُن کے رستہ میں حائل نہیں ہوں گی.روک نہیں بنیں گی.اِس جگہ ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے اور وہ یہ کہ اگر بنی اسرائیل کی ایمانی حالت اس درجہ تک گِری ہوئی تھی تو پھراﷲتعالیٰ نے ان کو خاص فضیلت کیوں دی، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی قوم کی حالت کا اندازہ صرف اس کے عوام کی حالت سے نہیں لگایا جاتا بعض دفعہ اس کی قیمت کا اندازہ اس کے خاص افراد کی حالت سے بھی لگایا جاتا ہے اور کبھی اس کی فطری قابلیت سے لگایا جاتا ہے.بنو اسرائیل کو دیکھو باوجود نبوت سے اس قدر دُور ہو جانے اور ہر قسم کے مظالم کا تختۂ مشق بنے ہوئے ہونے کے اپنی ذہانت اور عقل سے اب بھی وہ دنیا پر اقتصادی طور پر حکومت کر رہے ہیں اور ہر قسم کے علمی انکشافات میں پیش پیش ہیں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم قابلیت میں دوسری بہت سی اقوام سے ممتاز ہے.یہ تو ان کی فطری قابلیت کی دلیل ہے.ان کے خاص افراد کی قابلیت کا ثبوت یہ ہے کہ جس قدر انبیاء اس قوم میں آئے ہیں اَور کسی قوم میں نہیں آئے.اس قدر افراد کا جوہر خالص رکھنا اور خدا تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنا بھی یقیناً اس قوم کی فضیلت کا ثبوت ہے پس اس قوم کا خاص فضلوں کے لئے چُنا جانا غلط نہ تھا.نہ تحکّمانہ فعل تھا.یہ قوم واقعہ میں ان فضلوں کی مستحق تھی مگر اس میں جہاں خاص لوگوں کی بہتات اور فطری نور کی حدّت کی خوبی تھی وہاں یہ بھی نقص تھا کہ یہ اپنے فطری نور سے دنیوی ترقی کے حصول کے لئے مدد لیتے تھے نہ دینی ترقی کے لئے اور بوجہ عام طور پر ذہن رسا حاصل ہونے کے اپنے انبیاء سے حسد کرتے تھے اور ان کو خاص درجہ دینے پر تیار نہ ہوتے تھے.ان دونوں نقائص نے آخر ان کو روحانی میدان سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور یہ لوگ نبوت کا انعام کھو بیٹھے.خلاصہ یہ کہ یہود کا ایک ہی وقت میں خاص فضلوں کا وارث ہونا اور پھر خدا تعالیٰ کی ناراضگی کو بار بار اپنے پر نازل کرنا دو متضاد امور نہیں ہیں.ایک ہی وقت میں یہ دونوں امور جمع ہو سکتے ہیں اور بنی اسرائیل کے وجود میں جمع بھی ہوئے.آیت اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ ھَادُوْا کے معنی منفردانہ حیثیت سے یہ معنے تو قرآن کریم کی آیات کی ترتیب کے لحاظ سے ہیں لیکن اگر اس آیت کے مضمون پر منفردانہ نگاہ ڈالی جائے تو پھر اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے معنے مخصوص طور پر مسلمانوں کے بھی کئے جا سکتے ہیں.اس صورت میں یہ آیت ایک عظیم الشان پیشگوئی پر مشتمل ہے اور اِس میں مختلف مذاہب کے فیصلہ کی ایک آسان راہ بتائی گئی ہے اور وہ یہ کہ کوئی شخص اپنے پیاروں کو تباہ اور برباد نہیں
Page 153
ہونے دیتا نہ اُن کو دُکھ میں دیکھ سکتا ہے.پھر خدا تعالیٰ کب اپنے پیارے بندوں کو ذلیل اور رُسوا کرے گا.پس مختلف مذاہب کے فیصلہ کے لئے یہ طریق اختیار کیا جائے کہ جس مذہب کو الٰہی نصرت اور مدد ملے وہ الٰہی مذہب ہو گا اور جو خدا تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو وہ خدا تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب نہیں ہو سکتا.اس طریق کے مطابق اس وقت کے بعض مذاہب کا نام لے کر اﷲ تعالیٰ نے اِس آیت میں اُن لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہیں یعنی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی سچے مومن ہیں اور وہ جو یہودی ہیں اور نصاریٰ اور صابئین.یہ سب لوگ اپنے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اِس بات کے بھی مدّعی ہیں کہ جو اعمال ان کی قوم کرتی ہے وہی سچے اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں.اب اُن کی اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ اُن میں سے کون واقعہ میں اﷲ تعالیٰ کا پیارا اور سچا مومن ہے.ہم یہ طریق بتاتے ہیں کہ ان میں سے جو شخص واقعہ میں اﷲ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور یومِ آخر پر یقین رکھتا ہے اور وہ اعمال کرتا ہے جو واقعی اچھے ہیں وہ ضرور خوف و حزُن کی حالت سے نکل جائے گا اور اﷲتعالیٰ کے فضل سے ہر طرح کاآرام اُسے حاصل ہو جائے گا.آیت اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا....الخ میں اسلام کی ترقی کی طرف اشارہ یہ معیار جس حالت میں پیش کیا گیا ہے اُس کا علم اِس بات کے جاننے سے ہو سکتا ہے کہ سورۂ بقرہ ہجرت کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے اور اُن دنوں میں اسلام نہایت کمزور حالت میں تھا.خود اہلِ عرب مخالف تھے اور جان کے دشمن تھے.اہلِ مدینہ میں سے ایک زبردست جماعت صرف منافقانہ طور پر اسلام لے آئی تھی اور درپردہ اسلام کی تباہی کے لئے کوشاں تھی.یہود کے تین قبیلے مدینہ میں رہتے تھے اور تینوں اسلام کے سخت دشمن اور اسلام کے مٹانے کے درپے تھے.مسیحیوں کے مختلف قبائل مدینہ کے قُرب و جوار میں بستے تھے اور شام کی سرحد مدینہ سے چند منزل پر ہی تھی.اور وہاں کے باشندوں کے سینے اسلام کی عداوت سے لبریز تھے.مسلمانوں کی تعداد عورتیں اور بچے ملا کر تین چار ہزار سے زیادہ نہ تھی.ایسے وقت میں آنحضرت صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے منہ سے اﷲ تعالیٰ یہ کلمات نکلواتا ہے اور کل مخالفین کو جو نہ صرف تعداد میں ہی ہزاروں گُنا زیادہ تھے بلکہ مال، دنیا وی رُعب و داب اور حکومت اور سازوسامان کے لحاظ سے بھی آپ پر لاکھوں درجہ فضیلت رکھتے تھے.یہ پیغام دلواتا ہے کہ ہم سب اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم اﷲ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کرتے ہیں پس اس کا فیصلہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جو لوگ واقعہ میں ایسے ہیں ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ اُن کی مدد کرے.پس باوجود اس کے کہ تم زیادہ ہو اور ہر طرح امن و امان میں ہو.ہم کہتے ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ دُکھوں اور تکلیفوں سے نجات دے دے وہ سچا اور واقعہ میں
Page 154
خدا تعالیٰ کا پیارا ہے اور جو خوف وحزُن سے محفوظ ہوتے ہوئے اس میں پڑ جائے وہ ضرور غلطی پر ہے.مسیحی حکومتوں کا غلبہ اُن کے مذہب کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا اِس معیار پر کس مذہب کی صداقت ثابت ہوئی؟ اس کے جواب کے لئے ہمیں خود کچھ کہنے کی ضرورت نہیں.اسلام کے مخالفین کی لکھی ہوئی تاریخیں ہی اس بات پر کافی روشنی ڈال رہی ہیں کہ ہجرت کے پہلے ایک دو سال کے اندر کہ جب یہ دعویٰ کیا گیا ہے اسلام کی کیا حالت تھی اور اس کے بعد چند سال میں ہی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور وہ مسلمان جو چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغہ میں گھرے ہوئے تھے سطح زمین پر ٹڈی دل کی طرح پھیل گئے اور اُن کا خوف و حزُن امید اور خوشی سے بدل گیا اور ان کے دشمن جو پہلے سُکھ کی نیند سوتے تھے اور ملکوں کے حاکم تھے خوف و حُزن میں مُبتلا ہو گئے اور اس طرح خدا تعالیٰ کے فعل نے اس بات کی شہادت دے دی کہ مسلمانوں کی جماعت ہی وہ جماعت تھی جو واقعہ میں اﷲ تعالیٰ اور یومِ آخر پر ایمان رکھتی تھی اور اعمالِ صالحہ بجا لاتی تھی ورنہ دوسرے مذاہب کے پیروؤں کا ایمان ایک رسمی ایمان تھا اور اُن کے اعمال اﷲ تعالیٰ کے پسندیدہ نہ تھے.اِس معیار پر یہ اعتراض کرنا درست نہ ہو گا کہ اِس زمانہ میں مسیحی حکومتیں مسلمانوں پر غالب ہیں کیونکہ اﷲ تعالیٰ نے اس آیت میں مذہبی مقابلہ کے وقت اُس قوم کے خوف و حزُن سے نکلنے کا وعدہ کیا ہے جو واقعہ میں مومن اور اعمال صالحہ کو بجا لانے والی ہو اور اس زمانہ کے مسلمان بموجب حدیث نبی کریم صلی اﷲ علیہ وسلم اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں اور انہوں نے قرآن کریم پر عمل چھوڑ دیا ہے اور ان کی اس وقت وہی حالت ہو رہی ہے جو بنی اسرائیل کی مسیح ناصری ؑ کے وقت میں تھی.پس ان کا خوف و حزُن میں مبتلا ہونا بطور سزا ہے اور پیشگوئی کے مطابق ہے.ہاں یہ بھی وعدہ ہے کہ جب یہ لوگ مسیح موعود کو قبول کر کے پھر اس آیت کا مصداق بن جائیں گے تو ہر قسم کے خوف و حزُن سے بچ جائیں گے اور اُن کے دشمن ان کے مقابلہ میں ذلیل ہوں گے لیکن یہ غلبہ جسمانی نہیں بلکہ رُوحانی اسباب سے حاصل ہو گا اور تلوار کی بجائے دلائل و براہین سے اسلام کو غالب کیا جائے گا چنانچہ وہ مسیح موعودؑ پیدا ہو چکا ہے اور اُسے اور اس کے پیروؤں کو اﷲ تعالیٰ خارق عادت نشانات سے خوف و حزُن سے بچاتا اور ان کے دشمنوں کو ان کے مقابلہ میں شرمسار کرتا ہے.اس استدلال کا ردّ کہ صرف ایمان باللہ اور ایمان بیومِ آخر سے نجات ہو سکتی ہے اِس آیت کے معنے کرنے میں بعض لوگوں کو یہ دھوکا لگا ہے کہ چونکہ اِس جگہ صرف ایمان باﷲ اور ایمان بیومِ آخر کے ساتھ خوف و حزُن سے نجات کو وابستہ کیا ہے.پس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اس قوم کو جو اﷲ اور یومِ آخر پر ایمان لانے
Page 155
والی ہو.نجات یافتہ قرار دیتا ہے مگر یہ درست نہیں.ایمان باﷲ و یومِ آخر میں اسلام کے سب اصول شامل ہیں چنانچہ ایک دوسری جگہ اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ١ۙ وَّ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا.اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا (النسآء : ۱۵۱.۱۵۲) یعنی جو لوگ اﷲاور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اﷲ اور اُس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی اور راستہ بنا لیں.یہ لوگ ہی پکّے کافر ہیں.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اﷲ تعالیٰ پر ایمان کے اندر ہی رسولوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے اور رسولوں پر ایمان لانے میں اگر وہ کوئی کتاب لایا ہو تو اس پر ایمان لانا بھی داخل ہو گا.اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا ہے.وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (الانعام:۹۳) یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر (یعنی قرآن کریم پر) بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں.اس آیت سے ثابت ہے کہ یوم آخر پر ایمان میں قرآن کریم پر ایمان لانا اور عبادات کا بجا لانا بھی شامِل ہے پس اﷲ اور یومِ آخر پر ایمان لانا صرف ہستیٔ ءِ باری اور یوم آخر کا اقرار کرنا نہیں بلکہ اس کے اندر تمام وہ فروع بھی شامل ہیں جو ان سے متفرّع ہوتے ہیں.عَمِلَ صَالِحًا عملِ صالح کے معنے ہیں وہ عمل جو مناسب حال ہو.صَلَحَ کے معنے عربی زبان میں مناسب کے ہوتے ہیں یعنی جس میں کوئی نقص نہ ہو.کہتے ہیں صَالَحَہٗ وَافَقَہٗ اُس کے موافق ہو گیا.اور کہتے ہیں ھٰذَ ا یَصْلُحُ لَکَ.یہ کام تیرے مناسبِ حال ہے اور کہتے ہیں.اَصْلَحَ بَیْنَ القَوْمِ اُس نے قوم کی آپس میں موافقت کر ا دی.اعمال صالحہ سے مراد مناسب حال اعمال پس عملِ صالح کے معنے اُس کام کے ہیں جو ضرورت اور وقت کے مطابق ہو اور ایسا ہی کام فساد اور خرابی کو دُور کر سکتا ہے جو کام ضرورت اور وقت کے مطابق نہ ہو.اس سے فساد اور خرابی پیدا ہوتی ہے خواہ بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آتا ہو.جہاد کے وقت میں اگر کوئی نماز شروع کر دے یا نماز کے وقت میں صدقہ و خیرات بانٹنے لگ جائے یا رمضان کے ایاّم میں ایسے کاموں میں مشغول ہو جائے جو روزے کو باطل کر دیتے ہیں مثلاً اِرد گرد کے علاقوں میں تبلیغ کے لئے جانا شروع کر دے اور سفر کے عذر سے روزہ نہ رکھے تو ایسے شخص کے اعمال گو وہ تمام کے تمام اچھے ہی ہوں عملِ صالح نہیں کہلائیں گے اور اُن کا نیک نتیجہ پیدا نہیں ہو گا.قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی کامِل انسان کا ذکر ہے، وہاں عمل صالح کی ہی شرط رکھی گئی ہے اور کسی جگہ بھی
Page 156
عملِ خیر کی شرط نہیں رکھی، کیونکہ کوئی عملِ خیر بغیر عملِ صالح ہونے کے نفع نہیں دیتا.ہاں بعض بظاہر بُرے نظر آنے والے عمل عملِ صالح ہونے کی وجہ سے نفع دے جاتے ہیں مثلاً کسی شخص کے سر پر بچھو نظر آ جائے یا پگڑی میں کہیں سانپ بیٹھا ہوا دکھائی دے تو گو مارنا اور پیٹنا عملِ شرمیں سے ہے لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی زور سے ہاتھ مارے یا زور سے جوتی ہی مار دے اس خیال سے کہ اگر آہستہ سے اس چیز کے قریب گئے یا اس شخص کو بتایا جس کے سر پر وہ چیز بیٹھی ہے تو وہ زہریلا کیڑا اُسے ڈس لے گا.تو یہ عمل گوبظاہر بُرا ہو گا مگر عملِ صالح ہو گا اور اس لئے کرنے والے کو ثواب کا مستحق بنا دے گا.کوئی شخص کسی گڑھے کے پاس کھڑا ہو اور دوسرے شخص کو معلوم ہو جائے کہ اُس پر کوئی شخص فائرکرنے لگا ہے اور وہ اسے دھکّا دیکر گڑھے میں پھینک دے تو اگر گڑھے میں گرنا بندوق کا نشانہ بننے سے کم ضرر رکھتا ہو تو یہ گڑھے میں گِرا دینا ایک عملِ صالح کہلائے گا گو عام حالات میں یہ نیک کاموں میں سے نہیں.پس حقیقت یہی ہے کہ جو چیز انسان کو ثواب کا مستحق بناتی ہے وہ عملِ صالح ہے.اِس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر اوقات عملِ خیر ہی عملِ صالح ہوتے ہیں لیکن بعض وقت انسان عملِ خیر کو عملِ غیرصالح بنا دیتا ہے اُس وقت وہ عملِ خیر ثواب کا موجب نہیں رہتا.اسی طرح بعض دفعہ ضرورت کے ماتحت عملِ شرّ عملِ صالح بن جاتا ہے بشرطیکہ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو.اس وقت اسی پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے.رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم ایک دفعہ جہاد کے لئے تشریف لے گئے بعض صحابہؓ نے روزے رکھے ہوئے تھے وہ منزل مقصود پر پہنچ کر چوُر ہو کر گر گئے.مگر جو بے روزہ تھے.انہوں نے خیمے لگانے شروع کئے.کھائیاں کھودنی شروع کیں.لکڑیاں جمع کرنی شروع کیں اور وضو کے لئے پانی لائے.رسول کریم صلی اﷲ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا.آج بے روزہ روزہ داروں سے بڑھ گئے.اس واقعہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ گو روزہ ایک اچھا عمل ہے مگر ایسے وقت میں کہ اسلام کو انسان کی طاقت کی ضرورت ہو اُس وقت یہی روزہ ناجائز ہو جائے گا یا ادنیٰ عمل بن جائے گا ( یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روزے نفلی تھے فرضی نہ تھے فرضی روزہ سفر میں منع ہے).آج کل بد قسمتی سے مسلمانوں میں یہی خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ بظاہر عمل خیر کرنے والے تو ان میں بہت نظر آتے ہیں مگر عمل صالح کرنے والے بہت کم دکھائی دیتے ہیں.اسلام مصیبت میں ہے.چاروں طرف سے اُس پر حملے ہو رہے ہیں.اِس گِرے ہوئے زمانہ میں بھی لاکھوں مسلمان نماز اور اذکارِ الٰہی کے پابند ہیں لیکن وہ اپنا سارا وقت ذکر اور نماز میںہی خرچ کر دیتے ہیں.اُن کے مصلّے تو بیشک آباد ہیں مگر محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ وسلم کے گھر کے اُجڑنے کی اُن کو کوئی فکر نہیں.یقیناً یہ نمازیں اور یہ ذکر اُن کے مُنہ پر مارے جاتے ہیں اور چونکہ وہ اسلام کے گھر کی
Page 157
آبادی کا فکر نہیں کرتے.خدا اُن کے دلوںکو بھی اپنے جلوے سے آباد نہیں فرماتا.پھر لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو بظاہر مسلمانوں کی تعلیم اور مسلمانوں کی اقتصادی یا سیاسی حالت کی درستی میں لگے ہوئے ہیں لیکن نماز اور روزے سے غافل ہیں اس لئے اُن کے یہ کام محض سیاسی ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دین کی چاشنی ملی ہوئی نہیں اور جسم کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے اور رُوح کی ضرورت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے پس یہ کام بھی عملِ صالح نہیں رہے.مناسب حال کام وہی ہوتا ہے جس میں چاروں کونوں کا خیال رکھ لیا جاتا ہے.وہ مکان جس کی تین دیواریں ہوں اور ایک نہ ہو حفاظت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا کُجا یہ کہ ایک دیوار ہو اور تین نہ ہوں ضرورت تھی کہ ایک طرف اپنے عمل اور اپنے فعل سے اسلامی تعلیم کی خوبی کو دنیا پر ظاہر کیا جاتا تو دوسری طرف دلائل اور براہین کی تلواروں سے اسلام کی حفاظت کی جاتی.اگر یہ دونوں پہلو مدِّ نظر رکھ لئے جاتے تو اسلام کبھی کمزور نہیں ہو سکتا تھا.نہ مسلمان باغی بنتے نہ بُزدل اور بھگوڑے ہوتے بلکہ اعلیٰ اخلاق والے، اعلیٰ قربانیاں کرنے والے، شریف، متواضع،دلیر اور بہادر بیک وقت سب اخلاق کے مالک ہوتے اور دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکتی.یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صَلَحَ کا لفظ عربی زبان میں کبھی بُرے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا پس جھوٹ، چوری ڈاکہ وغیرہ قسم کے افعال پر وہ خواہ کسی مصلحت کے لئے ہی کیوں نہ ہوں اور کسی کے فائدہ ہی کے لئے کیوں نہ کئے جائیں عملِ صالح نہیں کہلا سکتے.وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ١ؕ خُذُوْا اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا تھا( اور کہا تھا کہ) جو مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۰۰۶۴ (کچھ )ہم نے تمہیں دیا ہےاسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ.حَلّ لُغَات.مِیْثَاقٌ.اَلْمِیْثَاقُ عَقْدٌ مُؤَکَّدٌ بِیَمِیْنٍ وَ عَہْدٍ.مِیَثَاقٌ کے معنے ہیں ایسا عہد کرنا جو قسم سے مُوکد ہو.( مفردات) رَفَعْنَا.رَفَعَ سے متکلّم مع الغیر کا صیغہ ہے.رَفَعَہٗ رَفْعًا کے معنے ہیں ضِدُّ وَضَعَہٗ.اس کو اوپر اُٹھایا بلند کیا.نیز کہتے ہیں.رُفِعَ لَہُ الشَّیْءُ اور مراد یہ ہوتی اَبْصَرَہٗ عَنْ بَعِیْدٍ اس نے فلاں چیز کو دُور سے دیکھا.(اقرب)
Page 158
اَلطُّوْرُ.اَلْـجَبَلُ طوُر کے معنے پہاڑ کے ہیں جَبَلٌ قُرْبِ اَیْلَۃَ یُضَافُ اِلٰی سَیْنَاءَ نیز ایک مخصوص پہاڑ کا نام بھی طور ہے جو طورِ سیناء کے نام سے مشہور ہے.(اقرب) اُذْکُرُوْا.امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور ذَکَرَ الشَّیْءَکے معنے ہیں حَفِظَہٗ فِیْ ذِھْنِہٖ کسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کر لیا.اُذْکُرُوْا امر حاضر جمع کا صیغہ ہے اور ذَکَرَ الشَّیْ ءَ (یَذْکُرُ ذِکْرًا وَ تَذْ کَارًا) کے معنے ہیں حَفِظَہٗ فِیْ ذِھْنِہٖکسی چیز کو اپنے ذہن میں یاد کر لیا اور جب ذَکَرَ الشَّیْ ءَ بِلِسَانِہٖ کہیں تو معنے ہوں گے قَالَ فِیْہِ شَیْئًا کہ اس نے کسی بات کے متعلق اپنی زبان سے کچھ کہا.اور ذَکَرَ لِفُلَانٍ حَدِیْثًا کے معنے ہیں قَالَہٗ لَہٗ کوئی بات بیان کی جب ذَکَرَ مَا کَانَ قَدْنَسِیَ کا فقرہ بولیں تو اس کے معنے ہوںگے فَطَنَ بِہٖ کسی بھولی ہوئی بات کی یاد تازہ ہو گئی.(اقرب) امام راغب لکھتے ہیں اَلذِّکْرُ تَارَۃً یُقَالُ وَیُرَادُ بِہٖ ھَیْئَۃٌ لِلنَّفْسِ بِھَا یُمْکِنُ لِلْاِنْسَانِ اَنْ یَّحْفَظَ مَا یَقْتَنِیْہِ مِنَ الْمَعْرِفَۃِ کہ ذکر کا لفظ بول کر کبھی نفس کی وہ ہیئت مراد لی جاتی ہے جس کے ذریعہ سے انسان کے لئے ممکن ہوتا ہے کہ وہ معلوم شدہ باتوں کو یاد رکھ سکے وَھُوَ کَا لْحِفْظِ اِلَّا اَنَّ الْحِفْظَ یُقَالُ اِعْتِبَارًا بِـاِحْرَازِہٖ وَالذِّکْرُ یُقَالُ اِعْتَبَارًا بِـاِسْتِحْضَارِہٖ.اور ان مذکورہ بالا معنوں میں ذکر کا لفظ حفظ کے لفظ کے ہم معنی ہے.ہاں حفظ اور ذکر ہر دو کے مفہوم میں تھوڑا سا امتیاز ہے.حفظ کسی شخص کے یاد کرنے پر اس وقت بولیں گے جب وہ ذہن میں بعض باتوں کو جمع کرتا چلا جائے اور ذکر اس کے اس طور پر یاد رکھنے کو کہیں گے کہ اس کو وہ باتیں ُمستحضر رہیں اور جب چاہے انہیں استعمال کر لے وَتَارَۃً یُقَالُ لِحَضُوْرِ الشَّیْ ءِ الْقَلْبَ اَوِالْقَوْلَ اور کبھی دل میں کسی امر کا خیال لانے یا زبان پر کسی بات کے لانے کا نام ذکر رکھا جاتا ہے وَلِذٰ لِکَ قِیْلَ اَلذِّکْرُ ذِکْرَانِ ذِکْرٌ بِالْقَلْبِ وَ ذِکْرٌ بِاللِّسَانِ اسی لئے کہتے ہیں کہ ذکر دو۲ طرح ہوتا ہے (۱) قلبی ذکر (۲) زبانی ذکر.وَکُلُّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا ضَرْبَانِ ذِکْرٌ عَنْ نِسْیَانٍ وَ ذِکْرٌ لَاعَنْ نِسْیَانٍ بَلْ عَنْ اِدَامَۃِ الْحِفْظِ کہ خواہ قلبی ذکر ہو یا قولی ہر دو۲ کی دو۲ دو۲ قسمیں ہیں (۱) بھول جانے کے بعد کسی بات کا یاد کرنا (۲) یا بغیر بھولنے کے یاد رکھنا (مفردات) پس اُذْکُرُوْا کے معنے ہوں گے.تم یاد کرو.بعض نے اُذْکُرُوْا مَافِیْہِ کے معنے اُدْرُسُوْا مَافِیْہِ کے بھی کئے ہیں یعنی جو کچھ اس میں ہے اس کو پڑھو.(لسان) لَعَلَّ.کے لئے دیکھو حل لغات سورۃ بقرۃ آیت ۵۳ جلد ھذا.تَتَّقُوْنَ.اِتَّقٰی یَتَّقِیْ سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے.اس کی مزید تشریح کے لئے دیکھیں حَلِّ لُغَات
Page 159
آیت نمبر ۴۹جلد ھٰذا.تفسیر.اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ کی تفسیر اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ سے وہ دس ۱۰ احکام اور ان کے ساتھ اُترنے والی دوسری تعلیم مراد ہے جو سیناء پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی.اس آیت میں ان احکام کی طرف بنی اسرائیل کو توجہ دلائی گئی ہے کہ ان احکام کو یاد کرو جو تمہیں اس وقت دیئے گئے تھے جبکہ تم سیناء کے نیچے کھڑے ہوئے تھے اور جن کے سُننے پر تم پیٹھ پھیر کر چلے گئے تھے اور تم نے خدا تعالیٰ کا کلام سُننے سے انکار کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم مر جائیں.مِیْثَاقَکُمْمیں میثاق کی اضافت ضمیر مخاطب کی طرف کرنے کی وجہ مِیْثَاقَکُمْ میں جو میثاق کی اضافت ضمیرِ جمع مخاطب کی طرف کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میثاق بنی اسرائیل میں ایک خاص شہرت رکھتا ہے اور اسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے.اس میثاق کے وقت بنی اسرائیل کے اُن تعلقات کی بنیاد رکھی گئی جو اُن میں اور اﷲ تعالیٰ میں قائم رہنے والے تھے اور اسی میثاق کے وقت اُن کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ شریعت لانے والا نبی بنو اسحاق میں سے نہیں بلکہ بنواسماعیل میں سے ہو گا.پس یہ میثاق چونکہ ایک خصوصیّت رکھتا تھا اس لئے اس کا نام ہی بنی اسرائیل کا میثاق رکھ دیا گیا اور اس وجہ سے ضمیر مخاطب کی طرف میثاق کی اضافت کی گئی.گویا یہ اضافت اُس عہد کی اہمیّت کی طرف توجہ دلانے کے لئے ہے اور ایسا محاورہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے بعض دفعہ ایک ماں باپ کے کئی بچّے ہوتے ہیں.کوئی بچّہ ماں کا لاڈلا ہوتا ہے.اُسے شرارت کرتے وقت اگر باپ کبھی دیکھ لے تو وہ اسے ماں کے پاس لے آتا ہے اور کہتا ہے لو تمہارا بچّہ ایسا کر رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ باپ کا بچہ نہیں یا دوسرے بیٹے ماں کے بیٹے نہیں بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس بچّہ سے ماں خاص تعلق رکھتی ہے.اسی محاورہ کے مطابق مِیْثَاقَکُمْ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے یہ معنی نہیں کہ اَور کوئی عہد بنی اسرائیل سے کیا ہی نہ گیا تھا.رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ میں لفظ طور کے معنے وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ.طُور کے معنے عبرانی زبان میں پہاڑ کے ہوتے ہیں خواہ کوئی پہاڑ ہو HEBREW AND ENGLISH LAXICON OF THE OLD TESTAMENT عہد ِ قدیم کی عبرانی ( انگریزی لغت) اور عربی زبان میں بھی طُور کے ایک معنے پہاڑ کے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ عربی زبان میں بھی طُور کے معنے پہاڑ کے ہیں.جب یہودیوں سے عربوں نے یہ سُنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے طُور پر کلام کیا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ شائد عبرانی زبان میں طُور اُس خاص پہاڑ کا نام
Page 160
تھا اس پہاڑ کو جبل الطور کہنے لگ گئے یعنی طُور پہاڑ.حالانکہ عبرانی زبان میں بھی طور کے معنے پہاڑ کے تھے اور عربی زبان میں بھی طُور کے معنے پہاڑ کے تھے اور جب عبرانی لوگ کہتے تھے طُور پر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں تو اس کے معنے محض اتنے ہوتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ایک پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا.قرآن کریم میں بھی گو طُور کا لفظ اسی رنگ میں استعمال کیا گیا ہے جس رنگ میں عربی میں استعمال ہوتا تھا اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا لیکن اُس میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ طُور پہاڑ کو کہتے ہیں نہ یہ کہ یہ کسی خاص پہاڑ کا نام ہے.چنانچہ قرآن کریم میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَآءَ (المؤمنون :۲۱) یا فرماتا ہے.وَ التِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ.وَ طُوْرِ سِيْنِيْنَ(التّین:۳،۲) ان دونوں حوالوں میں طُور لفظ کی سیناء کی طرف اضافت کر کے بتایا گیا ہے کہ طُوْر کا لفظ وضعِ لغت کے لحاظ سے کسی خاص پہاڑ کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی ہی پہاڑ کے ہیں اورموسیٰ کے طور سے مراد محض دشتِ سیناء کا ایک پہاڑ ہے.رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّوْرَ سے مراد پہاڑ کو بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر کھڑا کرنا نہیں اس آیت سے بعض لوگوں نے دھوکا کھایا ہے اور اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ پہاڑ کو بلند کر کے بنی اسرائیل کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا گیا تھا اور اس غلط مطلب کو لے کر راڈوِل صاحب نے بھی اسلام پر ایک اعتراض کر دیا ہے اور لکھتے ہیں کہ یہ غلطی خروج باب ۱۹ آیت ۱۷ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہود کو لگی ہے اور ان سے سن کر قرآن کریم میں نقل کر دی گئی ہے (خروج باب ۱۹ آیت ۱۷ کے الفاظ یہ ہیں ’’ اورموسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملاوے اور وَے پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے.‘‘ عربی کی بائبل میں یہ الفاظ ہیں وَ اَخَرَجَ مُوْسَی الشَّعْبَ مِنَ الْمَحَلَّۃِ لِمُلَاقَاۃِ ﷲِ فَوَقَفُوْا فِیْ اَسْفَلِ الْجَبَلِ ) لیکن اصل بات یہ کہ جس طرح بقول راڈوِل یہود نے خروج باب ۱۹ کی آیت ۱۷ کے معنے غلط سمجھے ہیں اسی طرح یہود کے قصوں پر یقین کر کے بعض لوگوں نے اس آیت کے وہ معنے کر دئے ہیں جو یہود میں طُور کے اُٹھائے جانے کے متعلق مشہور تھے.حالانکہ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ یہ عہد ایسے وقت میں ہوا جب تم دامنِ کوہ میں تھے اور یہ معنے عربی زبان کے محاورہ کے عین مطابق ہیں.جن دو لفظوں سے اس آیت کے معنے کرنے میں دھوکا لگا ہے وہ رفع اور فوق ہیں.رفع کے معنے اُٹھانے اور فوقکے معنے اوپر کے ہیں لیکن محاورۂ زبان میں یہ الفاظ صرف بلندی کے معنے میں بھی آتے ہیں جیسا کہ بخاری کی کتاب المناقب میں براء بن عاذبؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر خلیفۂ اوّل رضی اﷲ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا.مدینہ کی طرف آتے ہوئے جب گرمی سے سخت تکلیف ہوئی اور دوپہر کا وقت آگیا تو رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَۃٌ طَوِیْلَۃٌ لَھَا ظِلٌّ
Page 161
لَمْ تَأْتِ عَلَیْہِ الشَّمْسُ (بخاری کتاب المناقب بَابُ عَلَامَاتِ النُبُوَّةِ فِی الْاِسْلَام) جس کے لفظی معنے یہ ہیں کہ ایک لمبا پتھر ہمارے لئے اُٹھا یا گیا لیکن مراد یہ ہے کہ پاس ہی ایک اونچا پتھر نظر آیا.اسی طرح فوق کا محاورہ قرآن کریم میں موجود ہے جیسا کہ سورۂ احزاب میں آتا ہے.اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ اِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَ تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا.هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ زُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا.( الاحزاب :۱۱،۱۲) اس کے لفظی معنے تو یہ ہیں کہ دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے آ گیا لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ اونچی جانب کی طرف سے آ گیا.غرض اس آیت سے یہی مراد ہے کہ یہود کو طُور کے نیچے کھڑا کیا گیا اور بعض احکام ان کو دیئے گئے جن پر پابند رہنے کا اُن سے عہد لیا گیا جیسا کہ خروج باب ۱۹ آیت ۱۶ تا ۲۵ سے ثابت ہے.وہاں لکھا ہے ’’ اور یوں ہوا کہ تیسرے دن صبح کو بادل گرجے اور بجلیاں چمکیں اور پہاڑ پر کالی گھٹا امڈی اور قرنائی کی آواز بہت بلند ہوئی چنانچہ سارے لوگ ڈیروں میں کانپ گئے اور موسیٰ ؑ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے مِلاوے اور وَے پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور سب کو ہِ سینا پر زیرو بالادُھواں تھا کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کے اس پر اُترا اور تنور کا سا دُھواں اس پر سے اُٹھا اور پہاڑ سراسر ہل گیا اور جب قرنائی کی صدا بہت بڑھائی گئی اور بلند سے بلند ہوتی جاتی تھی موسیٰ نے کلام کیا اور خدا نے اسے ایک آواز سے جواب دیا اور خداوند کوہِ سینا پہاڑ کی چوٹی پر نازل ہوا اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا اورموسیٰ چڑھ گیا اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اُتر جا اور لوگوں کو تقیّد کر تا نہ ہووے کہ حدوں کو توڑ کے خداوند کے پاس دیکھنے کو آویں اور بہتیرے اُن میں ہلاک ہو جاویں اور کاہنوں کو بھی جو خداوند کے نزدیک آئے ہیں کہہ.اپنے کو پاک کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند اُن میں رخنہ ڈال دے.تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ لوگ کوہِ سینا پر آ نہیں سکتے کیونکہ تو نے تو ہمیں تاکید کر کے کہا ہے کہ پہاڑ کے لئے حدّیں مقرر کر رکھو اور اس کو پاک کرو.خداوند نے اسے کہا کہ چل نیچے جا اور تجھ کو پھر اُوپر آنا ہو گا.ُتو اور ہارون تیرے ساتھ.پرکاہن اور لوگ حدّیں توڑ کے خداوند پاس اوپر نہ آویں.نہ ہووے کہ اُن میں رخنہ ڈال دے چنانچہ موسیٰ لوگوں پاس تلے اُترا اور اُن سے کلام کیا.‘‘ اِس آیت میں طُور کے اُٹھانے کا فعل اﷲ تعالیٰ کی طرف اس لئے منسوب کیا گیا ہے کہ پہاڑ کے نیچے رہنے کا تاکیدی حکم اُن کو اﷲ تعالیٰ نے ہی دیا تھا چنانچہ خروج باب ۱۹ آیت ۲۱ میں لکھا ہے’’ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اُتر جا اور لوگوں کو تقیّد کرتا نہ ہووے کہ حدّوں کو توڑ کے خداوند کے پاس دیکھنے کو آویں اور بہتیرے ان میں ہلاک ہو جاویں.‘‘
Page 162
اس جگہ پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رَفع اور فَوْق کے دو الفاظ جو استعمال کئے گئے ہیں ان میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ طُور کا عہد ہمیشہ ہمیش کے لئے ساتھ رہے گا.گویا صرف اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ طُور کے نیچے یہ عہد لیا گیا تھا بلکہ تمثیلی زبان میں یہ کہا گیا ہے کہ طور ہمیشہ تمہارے سروں پر منڈلاتا رہے گا یعنی یہ عہد ایک دو دن کا عہد نہیں بلکہ اس عہد کا بنی اسرائیل کی قومی زندگی کے ساتھ دائمی تعلق ہے.خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ.اﷲ تعالیٰ نے شریعت موسویہ کی پہلی بنیاد دشتِ سینا کے ایک پہاڑ پر جس کا نام ہی اب طُور پڑ گیا ہے اور ہم بھی اب اس کو طُور کے نام سے ہی یاد کریں گے رکھی.خروج باب۱۹ اور باب۲۰ میں یہ سب واقعہ اور زلزلہ کے آنے کا ذکر ہے اور استثنا باب ۵ آیت ۲ سے جس کے یہ الفاظ ہیں کہ ’’ خداوند ہمارے خدا نے حُو رب میں ہم سے ایک عہد کیا.معلوم ہوتا ہے کہ دس احکام حورب کی چٹان پر سے بیان کئے گئے تھے اور اُس وقت بنی اسرائیل سے ان احکام پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا تھا.اسی طرح اِن دس احکام کے علاوہ اور احکام بھی دیئے گئے تھے جیسا کہ اَلْکِتَاب کے ماتحت خروج باب ۲۰ سے خروج باب ۳۱ تک کے حوالوں سے ثابت کیا جا چکا ہے دیکھئے تفسیر زیرآیت وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ (البقرة: ۵۴) یہ ایک عظیم الشان احسان کی بنیاد تھی لیکن جیسا کہ اگلی آیت سے ثابت ہے یہودیوں نے اس موقع پر بھی ناشکر گزاری سے کام لیا.اِس آیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یہ عہد جو اس وقت لیا گیا ہے انہیں چاہئے کہ اِس کو ہمیشہ کے لئے یاد رکھیں اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں اور اِس پر عمل کرتے رہیں تاکہ ہر قسم کے مصائب سے بچے رہیں.اِس تاکید کا ذکر استثناء باب ۵ میں بھی آتا ہے وہاں لکھا ہے :.’’ پھرموسیٰ نے سارے اسرائیل کو بُلایا اور اُنہیں کہا.اے اسرائیل یہ شرعیں اور احکام سن رکھو جنہیں مَیں آج تمہارے کانوں تک پہنچاتا ہوں تاکہ تم اُنہیں سیکھو اور حفظ کرو اور ان پر عمل کرو.‘‘( ۱ستثنا باب ۵ آیت ۱) لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ کا مضمون بائبل میں اسی طرح لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ کا مضمون بھی بائبل میں پایا جاتا ہے خروج باب۲۰ میں آتا ہے اگر تم اپنے اِس عہد پر قائم رہے اور ان احکام پر عمل کیا جو تمہیں دیئے گئے ہیں تو تم خدا تعالیٰ کے عذاب اور مصائب سے بچائے جاؤ گے چنانچہ لکھا ہے ’’ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم مت ڈرو اس لئے کہ خدا آیا ہے کہ تمہیں امتحان کرے اور تاکہ اُس کا خوف تمہارے سامنے ظاہر ہو کہ تم گناہ نہ کرو.‘‘ (خروج باب۲۰آیت۲۰)
Page 163
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ١ۚ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ پھر اس (واضح ہدایت) کے (مل جانے کے) بعد( بھی) تم نے پیٹھ پھیر لی اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ۰۰۶۵ نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میںسے ہو جاتے.حَلّ لُغَات.تَوَلَّیْتُمْ.تَولّٰی سے جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور تَوَلّٰی کے معنے ہیں.اَدْبَرَ پیٹھ پھیرلی تَوَلّٰی عَنْہُ.اَعْرَضَ وَ تَرَکَہٗ یعنی اس سے اعراض کیا اور اس کو چھوڑ دیا (اقرب ) پس تَوَلَّیْتُمْکے معنے ہوں گے.(۱) تم پیٹھ پھیر کر چلے گئے.(۲) تم نے اعراض کیا.تم نے اس کو چھوڑ دیا.فَضْلٌ.اَ لْاِحْسَانُ.فضل کے معنے احسان کے ہیں.وَالْاِ بْتِدَاءُ بِہٖ بِلَاعِلَّۃٍ کسی پر اس کے کام کے بغیر ابتداًء احسان کرنا فضل کہلاتا ہے.(اقرب ) اَلْخٰسِرِیْنَ.اَلْخٰسِرِیْن اور اَلْخَاسِرُوْنَ اَلْخَاسِرُ کی جمع ہے جس کے معنے نقصان اُٹھانے والے اور گھاٹا پانے والے کے ہیں.خَسِرَ التَّاجِرُ فِی بَیْعِہٖ (یَخْسِرُ) کے معنے ہیں وُضِعَ فِیْ تِجَارَتِہٖ تاجر کو تجارت میں گھاٹا ہوا ضِدُّرَبِحَ خَسِرَ کا لفظ نفع کے مخالف معنوں میں استعمال ہوتا ہے.خَسِرَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں ضَلَّ وَھَلَکَ گمراہ ہو گیا اور ہلاک ہو گیا (اقرب).عربی زبان میں یہ لفظ ہمیشہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے میں نے بڑی تحقیق کی ہے مگر مجھے نہیں ملا کہ یہ لفظ عربی کے استعمال میں کہیں بھی متعدّی استعمال ہواہو مگر عجیب بات ہے کہ تمام کے تمام مفسرین خَسِرُوْا کے معنے اَھْلَکُوْا کرتے ہیں لیکن تاج العروس والا کہتا ہے وَلَا یُسْتَعْمَلُ ھٰذَا الْبَابُ اِلَّا لَازِمًا کَمَا صَرَّحَ بِہٖ اَئِمَّۃُ التَّصْرِیْفِ کہ سارے اہلِ تصریف اس کو لازم ہی قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں کیونکہ قرآن کریم میں متعدی استعمال ہوا ہے لیکن حق یہ ہے کہ یہ لازم ہی ہے اور افسوس یہ ہے کہ ہماری لغتیں مذہبی اثر کے نیچے ہیں اور تفسیروں کے ماتحت لغت کو بھی کر دیا ہے جس سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا بلکہ نقصان پہنچا ہے اور کئی معارف قرآنیہ اس تصرف کی وجہ سے لوگوں کی نظر سے مخفی ہو گئے ہیں کاش کوئی شخص ہمت کر کے ایسی لغت تیار کرے جو تفسیروں کے اثر سے بالکل آزاد ہوتا کہ لوگ اس ناجائز دبائو سے بالکل آزاد ہو جائیں اور قرآن مجید کے سمجھنے میں لوگوں کو سہولت حاصل ہو جائے.
Page 164
خَسِرَ کے لفظ کے متعلق ہی اگر تفسیرو ںکا رُعب ماننے کی بجائے عربی کے قواعد پر نظر کی جائے تو اسے خلافِ محاورہ متعدّی بنانے کی ضرورت نہ تھی ہم اس کے معنے اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح سَفِہَ نَفْسَہُ کے کرتے ہیں یعنی حرفِ جار محذوف تصور کرتے ہیںاور جملہ کویوں تصوّر کرتے ہیں کہ سَفِہَ فِیْ نَفْسِہٖ یا تمیز خیال کرتے ہیں جو شاذو نادر کے طور پر معرفہ بھی آ جاتی ہے اسی طرح ہم خَسِرُوْا اَنْفُسَہُمْ کے بھی یہ معنے کر سکتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے بارہ میں گھاٹا میں پڑ گئے اور یہ معنے دوسرے معنوں سے زیادہ زور دار بھی ہو جاتے ہیں اور یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کا سب فریب خود اپنے ہی نفسوں کے خلاف پڑا ہے تمیز کی صورت میں بھی زور قائم رہتا ہے اور معنے اوپر والے ہی رہتے ہیں.تفسیر.خروج باب ۲۰ میں لکھا ہے:.’’اور سب لوگوں نے دیکھا کہ بادل گرجے، بجلیاں چمکیں، قرنائی کی آوازہوئی، پہاڑ سے دھواں اُٹھا اور سب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ہٹے اور دُور جا کھڑے رہے تب انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہی ہم سے بول اور ہم سُنیں، لیکن خدا ہم سے نہ بولے کہیں ہم مر نہ جاویں.(خروج باب۲۰آیت ۱۸،۱۹) اسی طرح استثنا باب ۵ میں لکھا ہے :.’’ خداوند نے تمہارے ساتھ روبرو پہاڑ کے اوپر آگ میں سے کلام کیا.اس وقت مَیں نے تمہارے اور خداوند کے درمیان کھڑے ہو کے خداوند کا کلام تم پر ظاہر کیا کیونکہ تم آگ کے سبب ڈر گئے تھے اور پہاڑ پر نہ چڑھے.‘‘ ( استثناباب ۵ آیت ۴.۵) ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ جب اﷲ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے کلام سے بالمشافہ مشرف کرنے کے لئے بُلایا تو وہ زلزلہ کو دیکھ کر ڈر کے پیچھے ہٹ گئے.پس تَوَلَّيْتُمْکے معنے اِس جگہ پر ظاہر میں ہٹنے کے ہیں.وہ لوگ بھاگ کر پیچھے چلے گئے اور خدا تعالیٰ کا کلام سُننے سے انکار کر دیا.اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اﷲ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اُس وقت تمہارا نام نبی کی امت میں سے کاٹ دیا جاتا اور تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاتے مگر اﷲ تعالیٰ نے اُس وقت تم کو کوئی سزا نہ دی.لیکن جیسا کہ استثنا باب۱۸ آیت ۱۸،۱۹ سے ثابت ہے ان کے کلام الٰہی سُننے سے انکار کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ ؑکی مانند جو آیندہ نبی ہو گا وہ ان میں سے نہیں ہو گا.بلکہ وہ ان کے بھائیوں یعنی بنو اسماعیل میں سے ہو گا.
Page 165
وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا اور تم ان لوگوں (کے انجام) کو جنہوں نے تم (اہل کتاب )میں سے( ہوتے ہوئے )سبت کے معاملہ میں زیادتی لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَۚ۰۰۶۶ فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ کی تھی یقیناًجان چکے ہو اس پر ہم نے ان سے کہا کہ( جاؤ) ذلیل بندر ہو جاؤ.پس ہم نے اس (واقع) کو ان يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا وَ مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ۠۰۰۶۷ (لوگوں)کے لئےبھی جو( وقوعہ کے وقت) موجود تھے اور اس (وقوعہ) کے بعد آنے والے لوگوں کے لئے (موجب) عبرت اور متقیوں کے لئے (موجب) نصیحت بنا دیا.حَلّ لُغَات.اِعْتَدَوْا.اِعْتَدَیٰ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اِعْتَدَیٰ کے معنے کے لئے دیکھو حلِّ لُغات سورۂ ھذا آیت نمبر ۶۲.اَلسَّبْتُ.سَبَتَ الرَّجُلُ ( یَسْبُتُ وَ یَسْبِتُ) سَبْتًاکے معنے ہیں.اِستَرَاحَ آرام کیا اور سَبَتَ الشَّیْ ءَ کے معنے ہیں قَطَعَہٗ کسی چیز کو کاٹا.سَبَتَ الرَّأْسَ.حَلَقَہٗ سر کو مونڈا.نیز سَبَتَ کے ایک معنی قَامَ بِاَمْرِالسَّبْتِ کے بھی ہیں.یعنی سبت کا دن منایا (اقرب) نیز اَلسَّبْتُ کے معنی ہیں اَلدَّ ھْرُ زمانہ.یَوْمٌ مِّنْ اَ یَّامِ الْاُسْبُوْعِ بَیْنَ الْجُمُعَۃِ وَ الْاَحَدِ ہفتہ کا دن (اقرب) سَبْت کو سَبْت اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن اہل کتاب کام وغیرہ چھوڑ دیتے تھے.خَاسِئِیْنَ.خَاسِئٌ کی جمع ہے جو خَسَأَُٔ سے بنا ہے، کہتے ہیں خَسَأْتُ الْکَلْبَ فَخَسَأَ اَیْ زَجَرْتُہٗ مُسْتَھِیْنًابِہٖ فَانْزَجَرَکہ مَیں نے کتےکو اس کے ذلیل ہونے کی وجہ سے دھتکارا اور وہ دُور ہو گیا (تاج ) خَسَأَ الرَّجُلُ الْکَلْبَ اَیْ طَرَدَہٗ کتّے کو دھتکارا.اَلْخَاسِیُٔ مِنَ الْکِلَابِ اَلْمُبْعَدُالْمَطْرُوْدُ لَایُتْرَکُ اَنْ یَدْنُوَمِنَ النَّاسِ یعنی جب خَاسِیٌٔ کا لفظ کسی کتّے کے متعلق استعمال کریں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ دُور کیا ہوا ،دھتکارا ہوا، جس کو لوگوں کے نزدیک نہ آنے دیا جائے.(اقرب) نَکَالًا.نَکَلَ بِفُـلَانٍ کے معنی ہیں صَنَعَ بِہٖ صَنِیْعًا یَحْذَرُغَیْرَہٗ اِذَارَءْاہُ کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا
Page 166
کہ دوسرا اس کو دیکھ کر ہوشیار ہو جائے.وَالنَّکَالُ اِسْمُ مَا یُجْعَلُ عِبْرَۃً لِلْغَیْرِ.ہر اس چیز کا نام نکال رکھیں گے جو کسی کے لئے عبرت کا موجب بن جائے.(اقرب) مَوْعِظَۃً.اَلْمَوْعِظَۃُ (نصیحت) وَعَظَ کا اسم مصدر ہے.کہتے ہیں وَعَظَہٗ: نَصَحَہٗ وَذَکَّرَہٗ مَایُلَیِّنُ الْقُلُوْبَ مِنَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ یعنی اس کو ایسی نصیحت کی جو دل کو نرم کر دے کہیں سزا کی باتیں بتا بتا کر اور کہیں کامیابی کے راستے بتا بتا کر.وَ فِی الْمِصْبَاحِ مَایَسُوْقُہٗ اِلَی التَّوْبَۃِ اِلَیﷲِ وَاِصْلَاحِ السِّیْرَۃِ وَ اَمْرِہٖ بِالطَّاعَۃِ اور مصباح کے مصنّف نے وَعَظَ کے یہ معنی لکھے ہیں کہ ایسی باتیں کسی کو سُنانا جو اس کو اﷲ کی طرف رجوع کروانے اور عادات و اطوار کو درست بنانے اور خدا کے احکام کی فرمانبرداری کروانے کا موجب ہوں(اقرب) خلیل نحوی ادیب نے وَعْظٌ کے معنی ھُوَ التَّذْکِیْرُ بِالْخَیْرِ فِیْمَـا یَرِقُّ لَہُ الْقَلْبُ کے کئے ہیں یعنی وعظ ایسی باتوں کے یاد دلانے کو کہتے ہیں جن کے سُننے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے (مفردات) اَلْمَوْعِظَۃُ: کَلَامُ الْوَاعِظِ مِنَ النُّصْحِ وَالْحَثِّ وَالْاِنْذَارِ یعنی اَلْمَوْعِظَۃُ اس کلام کو کہتے ہیں جو نہایت اخلاص پر مبنی ہو اور نیک باتوں کی طرف ترغیب دے اور بُری باتوں سے ڈرائے.(اقرب) اَلْمُتَّقِیْنَ.اَلْمُتَّقِیْنَ اور اَلْمُتَّقُوْنَ یَتَّقِیْ سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے.اَلْمُتَّقِیْنَ.متقی کی جمع ہے جو اِتَّقٰی کا اسم فاعل ہے.اِتِّقَاءٌ وَقٰی سے بابِ اِفْتِعال کا فعل ماضی ہے وَقٰـی کے معنے ہیں بچایا، حفاظت کی.اور اِ تَّقـٰی کے معنے ہیں.بچا.اپنی حفاظت کی (اقرب) مگر اس لفظ کا استعمال دینی کتب کے محاورہ میں معصیت اور بُری اشیاء سے بچنے کے ہیں اور خالی ڈر کے معنو ںمیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا.وَقَایَۃٌ کے معنی ڈھال یا اس ذریعہ کے ہیں جس سے انسان پنے بچائو کا سامان کرتا ہے بعض نے کہا ہے کہ اتقاء جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے تو انہی معنوں میں آتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی نجات کے لئے بطور ڈھال بنا لیا.قرآن کریم میں تقویٰ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بارہ میں حضرت ابوہریرہؓ سے کسی نے پوچھا تو انہوںنے جواب دیا کہ کانٹوں والی جگہ پر سے گزرو تو کیا کرتے ہو ،اس نے کہا یا اس سے پہلو بچا کر چلا جاتا ہوں یا اس سے پیچھے رہ جاتا ہوں یا آگے نکل جاتا ہوں.انہوں نے کہا کہ بس اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقام پر کھڑا نہ ہو اور ہر طرح اس جگہ سے بچنے کی کوشش کرے ایک شاعر (ابن المعتز) نے ان معنوں کو لطیف اشعار میں نظم کر دیا ہے وہ کہتے ہیں.؎ خَلِّ الذُّنُوْبَ صَغِیْرَھَاوَ کَبِیْرَھَا ذَاکَ التُّقٰی
Page 167
وَاصْنَعْ کَمَاشٍ فَـوْقَ اَرْ ضِ الشَّوْکِ یَحْذَرُمَایَرٰی لَا تَحْقِرَنَّ صَغِیْرَۃً اِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصٰی (ابن کثیر سورۃ بقرۃ زیر آیت ۳) یعنی گناہوں کو چھوڑ دے خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے یہ تقویٰ ہے اور تو اُس طریق کو اختیار کر جو کانٹوں والی زمین پر چلنے والا اختیار کرتا ہے یعنی وہ کانٹوں سے خوب بچتا ہے اور تو چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھ کیونکہ پہاڑ کنکروں سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں.تفسیر.سبت کے معنے سبت کے معنے حلِّ لُغات میں بتائے جا چکے ہیں کہ زمانۂ راحت.کاٹنے.مونڈنے.سبت کا دن منانے اور ہفتہ کے دن کے ہوتے ہیں.یہ سارے معنی ہی اس آیت پر چسپاں ہو سکتے ہیں.اگر تو اس آیت کو گزشتہ آیات سے ملا کر نہ پڑھا جائے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ جب ہم نے تم کو مال و دولت اور آرام و آسائش دی تو تم نے شرارتیں شروع کر دیں اس لئے ہم نے تم کوذلیل کر دیا.اور اگر سابق آیات سے ملا کر پڑھا جائے تو پھر اس کے معنے یہ ہوں گے کہ طُور کے موقع پر جو احکام تمہیں دئے گئے تھے اُن میں سے ایک حکم سبت منانے کا بھی تھا.تم نے اُس حکم کی بھی نافرمانی کی.سبت منانے کا حکم بائبل میں سبت کا ذکر استثنا باب ۵ آیت ۱۲ تا ۱۵میں آتا ہے.لکھا ہے:.’’ سبت کے دن کو یاد کرتا کہ تو اُسے مقدّس جانے جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم کیا ہے.چھ دن تک تو محنت کر اور اپنے سب کام کیا کر.پر ساتواں روز خداوند تیرے خدا کے سبت کا ہے تو اُس دن کوئی کام نہ کر ،نہ تو، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیری کوئی مواشی اور نہ مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، تاکہ تیرا غلام اور تیری لونڈی تیری طرح سے آرام کریں.یہ بھی یاد کر کہ تو مصر کی زمین میں غلام تھا.اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بڑھائے ہوئے بازو سے تجھے نکال لایا.اس لئے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا کہ تو سبت کے دن کی محافظت کر.‘‘ اِسی قسم کا مضمون خروج باب ۲۰ آیت ۸ تا ۱۱ میں بھی ہے.اوپر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہےکہ یہ ٹکڑا واقعی اُن ٹکڑوں میں سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی میں سے اب تک محفوظ چلے آتے ہیں.انسانی اعمال کی حکمت اور غرباء کی خبرگیری کی نہایت اعلیٰ درجہ کی تعلیم اس میں موجود ہے.
Page 168
سبت جس کا عبرانی لہجہ ثبات ہے اس کے معنے عربی کی طرح (دیکھو حَلِّ لُغَات ) عبرانی میں بھی آرام کے ہیں.اس کے علاوہ اس کے معنی عبرانی زبان میں قطع کرنے اور ختم کرنے کے بھی ہیں.(انسا ئیکلوپیڈیا ببلیکا زیر لفظ SabathنیزHEBREW AND ENGLISH LAXICON OF THE OLD TESTAMENT ) اور عربی زبان میں بھی یہ معنے پائے جاتے ہیں.کہتے ہیں.سَبَتَ الشَّیْ ءَ قَطَعَہٗ اس چیز کو کاٹا.سَبَتَ رَأْسَہٗ حَلَقَہٗ.اس کا سرمونڈا.عبرانی زبان کے واقفوں کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ ہفتے کے دن کا نام سبت آرام کی وجہ سے نہیں رکھا گیا.بلکہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ اُس ہفتہ کے کام کو ختم کرتاہے.پُرانی بابلی زبان میں سَبَۃً دعائے توبہ کو کہتے تھے اس لئے بعض (جیبسن) کے نزدیک یہ اسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنے یہ ہیں کہ یہ توبہ اور دعا کا دن ہے.(انسا ئیکلو پیڈیا ببلیکا جلد ۴ کالم نمبر۴۱۷۳) جیسا کہ بائبل کے حوالہ سے ظاہر ہے سبت کا دن غلاموں، ملازموں اور قبیلہ کے لوگوں کو آرام دلانے اور عبادت کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا.یہ دونوں حکمتیں نہایت اہم ہیں اور یقیناً اس قابل ہیں کہ ان کو مدّ نظر رکھا جائے.یہودیوں میں سبت ہفتہ کو منایا جاتا تھا اور بائبل سے ہفتہ کا دن ہی اِس بات کے لئے ثابت ہے ( اس لئے سبت کے معنے ہی ہفتہ کے دن کے ہو گئے ورنہ اصل معنے سبت کے یہی ہیں کہ جس دن روز مرّہ کے کام چھوڑ دیئے جائیں اور اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بنو اسرائیل کا سبت ہفتہ کو ہوتا ہے اور مسلمانوں کا جمعہ کو) کیونکہ لکھا ہے جمعہ کے دن خدا تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے کا کام ختم کیا اور ہفتہ کے دن آرام کیا اور اسی کی یاد میں یہودیوں کو سبت منانے کا حکم دیا چنانچہ آتا ہے ’’ خداوند نے چھ دن میں آسمان اور زمین، دریا اور سب کچھ جو اُن میں ہے بنایا اور ساتویں دن آرام کیا اس لئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدّس ٹھہرایا.‘‘ ( خروج باب ۲۰ آیت ۱۱ نیز دیکھو پیدائش باب ۲ آیت ۲ تا ۵) عیسائیوں کا ہفتہ کے دن کی بجائے اتوار کو چھٹی کا دن منانے کی وجہ عیسائیوں نے بھی سبت کی اہمیت کو تو تسلیم کیا ہے لیکن اس کے لئے اتوار کا دن قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض یوروپین اقوام اور بادشاہوں نے جب عیسائیت کی طرف رغبت ظاہر کی تو انہوںنے اپنے عیسائی ہونے کی ایک شرط یہ رکھی کہ چھٹی کا دن اتوار قرار دیا جائے اور ان لوگوں کو عیسائی بنانے کے لالچ میں پادریوں نے اُن کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور اس طرح سبت کی بے حُرمتی میں وہ یہود سے بھی بڑھ گئے کیونکہ یہود تو سبت کے دن کبھی کبھی کوئی فائدے کا کام کر لیا کرتے تھے لیکن عیسائیوں نے ہفتہ کو ہمیشہ کے لئے کام کا دن قرار دے دیا اور آرام کے دن کے لئے اتوار کو چن
Page 169
لیا.اگر خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایسا ہوتا تو یہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہ تھی مگر یہ جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت نہیں ہوا.اپنی مرضی سے اور حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد ہوا.حضرت مسیح ناصری ؑ خود سبت کا احترام کیا کرتے تھے.گو یہودیوں میں جو غلو سبت کے متعلق پیدا ہو گیا تھا اس کے وہ مخالف بھی تھے چنانچہ وہ فرماتے ہیں ’’ سبت کا دن انسان کے واسطے ہوا نہ انسان سبت کے دن کے واسطے‘‘ (مرقس باب۲ آیت ۲۷) اس کے یہی معنی ہیں کہ اگر حقیقی ضرورتیں پیش آ جائیں تو اُس میں سبت کے تفصیلی احکام کا لحاظ نہیں رکھا جا سکتا اور نہ دین کے کاموں کو سبت روک سکتا ہے.یہودیوں میں یہ بیہودہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ سبت کے دن تبلیغ کرنی، وعظ کرنا اور دوسرے نیکی کے کام کرنے بھی ناجائز ہیں حالانکہ سبت کے دن تو صرف دنیوی کاموں سے روکا گیا تھا.انجیل میں سبت منانے کا حکم اور عیسائیوں کا اس کی خلاف ورزی کرنا ابتدائی ایّام میں عیسائی اقوام برابر سبت کا دن مناتی چلی آئی ہیں ( دیکھو انسائیکلوپیڈیا ببلیکا زیر لفظ Sabathاور جیوش انسائیکلوپیڈیا زیر لفظ Sabath and Sunday) ہاں حواریوں کے زمانہ سے ہی غیر یہودی قوموں میں اتوار کا احترام بھی جو کہ آرین نسلوں کا مقدس دن ہے ساتھ ساتھ جاری تھا چنانچہ پولوس نے قُرنتیوں کے نام جو پہلا خط لکھا اُس میں تحریر ہے کہ : ’’ ہر ہفتہ کے پہلے دن ( یعنی اتوار کو) تم میں سے ہر کوئی اپنی آمدنی کے موافق جہاں تک فائدہ اُٹھایا کچھ جمع کر کے اپنے پاس رکھے تاکہ جب میں آؤں تو چندہ کرنا نہ پڑے.‘‘ (باب ۱۶ آیت ۲) اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اتوار کے دن وہ لوگ چھٹی کیا کرتے تھے.اسی طرح اعمال باب ۲۰ میں پولوس کے ذکر میں لکھا ہے ’’ اور ہفتہ کے پہلے دن (اتوار کو) جب شاگرد روٹی توڑنے کو اکٹھے آئے پولس نے کہ دوسرے دن جانے کو تھا ان کے ساتھ کلام کیا اور اپنا کلام آدھی رات تک بڑھایا.‘‘ ( آیت ۷) اس حوالہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ غیر یہودی قوموں کے اجتماع عام طور پر اتوار کے دن ہوا کرتے تھے شائد اس لئے کہ وہ اُن کی قومی چھٹی کا دن تھا.آج کل بھی جہاں جہاں مسلمان انگریزی حکومت کے ماتحت ہیں اُنہیں اپنے جلسے اتوار کے دن کرنے پڑتے ہیں کیونکہ یہی چھٹی کا دن ہے.بعض مصنّفین لکھتے ہیں کہ اتوار کے دن عیسائیوں نے سبت کا منانا اس لئے شروع کیا تاکہ غیر یہودی قوموں میں اُن کی مخالفت نہ پیدا ہو.بر نباس کے خط میں لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیح اس دن مُردوں میں سے جی اُٹھے تھے.( جیوش انسا ئیکلو پیڈیا زیر لفظ Sabath and Sunday) بہرحال کوئی وجہ بھی ہو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف تھا.اسلام نے بھی سبت کا ایک دن مقرر فرمایا ہےاور وہ جمعہ کا دن ہے.جمعہ کا دن کسی قیاس کے مطابق مسلمانوں نے مقرر نہیں کیا بلکہ اﷲ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مقرر کیا ہے اس لئے ان پر وہ اعتراض نہیں پڑتا جو
Page 170
عیسائیوں پر پڑتا ہے.اسلام نے جمعہ کے دن کے لئے یہ خصوصیّتیں مقرر فرمائی ہیں.اُس دن چھٹی رکھی جائے.عبادت زیادہ کی جائے اُسے قومی اجتماع کا دن بنایا جائے.نہایا دھویا جائے.صفائی کی جائے.مریضوں کی عیادت کی جائے.اسی طرح اور قومی اور تمدّنی کام کئے جائیں.ہاں جمعہ کی نماز سے فراغت کے بعد اجازت دی گئی ہے کہ لوگ اپنے مشاغل میں لگ جائیں مگر زیادہ مناسب اسی کو قرار دیا ہے کہ بعد میں بھی وہ ذکر الٰہی میں مشغول رہیں.سبت کی بے حرمتی کی سزا میں مسلمانوں کے لئے عبرت افسوس ہے کہ مسلمانوں نے بھی سبت کی قدر نہیں جانی اور جمعہ کی نماز سوائے بڑے شہروں کے ایک عرصہ تک ہندوستان سے بالکل مٹی رہی.اب کچھ کچھ اس طرف توجہ ہے مگر اب بھی سَو میں سے ایک مسلمان صرف جمعہ کی نماز بھی ادا کرنے کے لئے تیار نہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ.گورنمنٹ نے بصد مشکل بانی ء سلسلہ احمدیہ کے میموریل اور جماعت احمدیہ کی کوششوں کے بعد جمعہ کی نماز کے لئے ایک گھنٹہ کی چھٹی منظور کی ہے مگر افسوس کہ مسلمان اب بھی اس سے فائدہ نہیں اُٹھاتے اور بعض جگہ پر تو دوسرے مسلمان صاف طور پر گورنمنٹ کے افسروں سے کہہ دیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لئے چھٹی کی درخواست محض احمدیوں کی شرارت ہے ہم لوگ اس میں شامل نہیں.عیسائیوں میں اب پھر یہ تحریک شروع ہے کہ اتوار کی جگہ ہفتہ کو سبت منایا جائے.یہ لوگ سیونتھ ڈے ایڈونٹس(Seventh day Advents)کہلاتے اور اتوار کی بجائے ہفتہ کو سبت مناتے ہیں.سبت کے دن یہودیوں کی نافرمانیاں کرنے کا ذکر قرآن مجید میں اِس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے سبت کے دن زیادتیاں کیں.وہ زیادتیاں کیا تھیں.اس کا جواب خود قرآن کریم میں ہی مذکور ہے.اﷲتعالیٰ فرماتا ہے.وَ سْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ١ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّ يَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ١ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ١ۛۚ كَذٰلِكَ١ۛۚ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.(الاعراف : ۱۶۴)یعنی اُن سے پوچھ اُس بستی کی نسبت جو سمندر کے کنارے پر تھی جبکہ وہ زیادتی کیا کرتے تھے سبت کے متعلق.اُس وقت کہ ان کی مچھلیاں اُن کے سبت کے دن سامنے آ جاتی تھیں اور جس دن سبت نہ ہوتا تھا سامنے نہ آتی تھیں.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی لوگ تجارتی فوائد کو مدّنظر رکھتے ہوئے ہفتہ کو مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے اس آیت میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ ہفتہ کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں یہ کسی غیر معمولی معجزے کا ذکر نہیں جیسا کہ بعض مفسّرین نے سمجھا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ بعض مخیّرلوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے مقدّس ایّام میں
Page 171
اپنے جانوروں وغیرہ کو بھی کچھ کھانا ڈال دیتے ہیں اور جانور بھی ان اوقات کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں.معلوم ہوتا ہے سبت کے دن نیک لوگ کنارے پرآٹا وغیرہ ڈال دیتے ہوں گے تاکہ یہ اُ ن کی طرف سے صدقہ ہو.مچھلیاں اُس دن خصوصیّت کے ساتھ وہاں جمع ہو جاتی ہوں گی.جب شریروں نے یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے سبت کے دن مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں.ہندو لوگ بھی اپنے مقدّس گھاٹوں پر آٹا اور دانے وغیرہ ڈال دیتے ہیں.ان گھاٹوں پر جا کر دیکھو کہ ان اوقات میں جبکہ آٹا یا دانے ڈالے جاتے ہیں مچھلیاں اتنی کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ تعجب آتا ہے اور اُس جگہ سے ہٹ کر یا دوسرے اوقات میں دیکھو تو مچھلیاں نظر ہی نہیں آتیں.بائبل میں سبت کے متعلق یہود کی بعض نافرمانیوں کا ذکر بائبل میں بھی سبت کے متعلق یہود کی بعض نافرمانیوں کا ذکر آتا ہے.نحمیاہ باب ۱۳ میں لکھا ہے: ’’ اُنہی دنوں میں مَیں نے کتنوں کو دیکھا جو سبت کے دن انگوروں کو کولہوؤں میں کچلتے ہیں اور پوُلے باندھتے اور گدھے لادتے ہیں.اسی طرح مَے اور انگور اور انجیر اور سارے بوجھ دیکھے جنہیں وَے سبت کے دن یروشلم میں لائے اور جس دن وے سیدھا بیچنے لگے اُن کی بدی اُن پر جتائی اور وہاں صور کے لوگ بھی ٹکتے تھے جو مچھلی اور ہر طرح کی چیزیں لا کے سبت کے دن یہوداہ اور یروشلم کے لوگوں کے ہاتھ بیچتے تھے.‘‘ (آیت ۱۵،۱۶) سبت کی بے حرمتی کا ذکر یرمیاہ باب ۱۷.آیت ۱۹ تا ۲۷.اور حزقی ایل باب ۲۲ آیت ۸ میں بھی آتا ہے.كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَکی تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات کے پیش نظر اس آیت کے معنے کرنے میں بعض مفسّرین نے دھوکا کھایا ہے اور قِرَدَۃ کے لفظ سے جس کے معنی بندر کے ہیں یہ سمجھا ہے کہ اس آیت میں سبت کے حکم کی نافرمانی کرنے والی قوم کے بندر بن جانے کی خبر دی گئی ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں.کیونکہ قرآن کریم میں یہ واقعہ اِس جگہ کے علاوہ دو ۲ اور جگہ پر بھی بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں مقامات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ درحقیقت بندر نہ بنے تھے بلکہ بندر کا لفظ تشبیہ ا ورمثال کے لئے آیا ہے.چنانچہ سورۂ مائدہ آیت ۶۱،۶۲ میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ١ؕ مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ١ؕ اُولٰٓىِٕكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ.وَ اِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْۤا اٰمَنَّا وَ قَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ١ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ.(المائدة:۶۲،۶۱) یعنی ان لوگوں سے کہہ دے کہ کیا مَیں تم کو اﷲ تعالیٰ کے نزدیک اس جماعت سے زیادہ بُری جزا پانے والی جماعت کی خبر دُوں.یہ وہ لوگ ہیں جن پر اﷲتعالیٰ نے لعنت کی اور اُن پر غضب کیا اور اُن میں سے ایک جماعت کو بندر اور سؤر بنا دیا اور جو
Page 173
کو سن کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا تعجب ہے کہ یہود سے مسخ ہو کر بندر بننے والے ہی رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے پاس آتے ہوں.اوّل تو جو تشریحات قرآن کریم کی بتائی ہوئی اوپر بتائی گئی ہیں وہ اس توجیہ کی اجازت ہی نہیں دیتیں.دوسرے جو لوگ اَ ئمہ سابق میں سے اس قسم کے مسخ کے قائل ہیں وہ خود بھی اسے تسلیم نہیں کرتے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے زمانہ تک زندہ رہے تھے.ابن ابی حاتم نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے فَجُعِلُوْا قِرَدَۃً فَوَاقًا ثُمَّ ھَلَکُوْا مَا کَانَ لِلْمَسْخِ نَسْلٌ یعنی یہود ذرہ سی دیر کے لئے بندر بنائے گئے تھے پھر ہلاک ہو گئے تھے اور مسخ شدہ کی نسل نہیں چلا کرتی.اسی طرح ضحّاک نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے.فَمَسَخَھُمُ اللہُ قِرَدَۃً بِمَعْصِیَتِہِمْ یَقُوْلُ اِذًالَایُحْیَوْنَ فِی الْاَرْضِ اِلَّا ثَـلَاثَۃَ اَ یَّامٍ قَالَ وَلَمْ یَعِشْ مَسْخٌ قَطُّ فَوْقَ ثَـلَا ثَۃِ اَ یَّامٍ وَلَمْ یَاْکُلْ وَلَمْ یَشْرَبْ وَ لَمْ یَنْسُلْ (ابن کثیر زیر آیت ھٰذا )یعنی ضَحَّاک حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ یہود کو اﷲ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب سے مسخ کر دیا پھر فرماتے تھے ایسے لوگ دنیا کے پردہ پر تین دن سے زیادہ زندہ نہ رہتے تھے پھر ضحّاک نے کہا کہ کبھی کوئی مسخ شدہ مخلوق تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی اور مسخ ہونے کے بعد نہ وہ کھانا کھاتی ہے اور نہ وہ پانی پیتی ہے اور نہ اس کی نسل چلتی ہے.اسی حوالہ سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مسخ کے قائل ہیں ان کے نزدیک مسخ کے بعد تین دن سے زیادہ کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا.جب یہ مسئلہ ہے تو جن مسخ شدہ لوگوں کے بارہ میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ قیامت تک ان پر لوگ مسلّط رہیں گے اور وہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے پاس بھی آیا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے وہ جسمانی طور پر مسخ شدہ کس طرح ہو سکتے ہیں.بفرضِ محال اگر جسمانی مسخ کو مان لو تو بھی قرآن کریم میں جن لوگوں کے مسخ ہونے کا ذکر ہے ان کی نسبت تو اوپر کے حوالوں کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ وہ تو روحانی طور پر مسخ ہوئے تھے جسمانی طور پر بندر سؤر ہرگز نہ بنے تھے.قرآن کریم کی مذکورہ بالا تشریح کے علاوہ ایک اور بھی ثبوت ہے جس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جگہ بندر سے حقیقی بندر مراد نہیں ہیں اور وہ قواعدِزبان کی شہادت ہے.عربی گرامر کا یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ و ن اور ی ن کو صرف اُن جمع کے صیغوں کے آخر میں لگایا جاتا ہے جو ذوی العقول کے متعلق ہوں یا جو ان کی صفات ہوں اور چونکہ اﷲ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قِرَدَۃً کی صفت خَاسِئِیْنَ بیان فرمائی ہے جس کے آخر میں ی ن ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قِرَدَۃً سے وہ بندر مراد نہیں جو حیوانات کی قسم سے ہیں کیونکہ اگر وہ مراد ہوتے تو قِرَدَۃً کی صفت بجائے خَاسِئِیْنَ کے خَاسِئَۃً آتی.لیکن چونکہ قِرَدَۃً کی صفت خَاسِئِیْنَ آئی ہے اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندر
Page 174
حقیقی بندرنہ تھے.علماء سلف کا اس بات کی تائید کرنا کہ یہودی حقیقی بندر نہ بنے تھے جو معنے ہم نے اوپر کئے ہیں وہ علماءِ سلف سے بھی مروی ہیں چنانچہ مجاہد جو مفسّرین کے سردار مانے جاتے ہیں اور تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں مُسِخَتْ قُلُوْبُھُمْ وَ لَمْ یُمْسَخُوْا قِرَدَۃً وَاِنَّمَا ھُوَ مَثَلٌ ضَرَبَہُ اللہُ لَہُمْ (ابن کثیر و درمنثورزیر آیت ھٰذا) یعنی ان کے دل مسخ کر دیئے گئے تھے وہ خود مسخ نہیں کئے گئے اور اﷲ تعالیٰ نے یہ بات صرف ایک مثال کے طور پر بیان فرمائی ہے.ابوالعالیہ کہتے ہیں کہ قِرَدَۃً خَاسِئِیْنَ کے معنے اَذِلَّۃً صَاغِرِیْن کے ہیں یعنی ذلیل ،رسوا.قتادہ اور ربیع اور ابو مالک کا بھی یہی قول ہے ( لغت میں بھی کہتے قَرَدَفُلَانٌ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں ذلیل ہو گیا) (ایضاً) اسی طرح دوسرے علماء نے بھی کہا ہے.جُعِلَتْ اَخْـلَاقُھُمْ کَاَخْـلَاقِھَا (مفردات) کہ ان کے اخلاق بندروں جیسے ہو گئے تھے.یہودیوں میں بندروں کی تین خاصیات کا پیدا ہو جانا بندر بنا دینے سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی قرآن کریم سے ہی ظاہر ہے.اوّل تو وہ ذلیل ہو گئے جس طرح بندروں کو لوگ پکڑ کر نچاتے پھرتے ہیں اور جس طرح قلندر اُن سے کہتا ہے اُن کو کرنا پڑتا ہے اسی طرح اُن پر بھی ایسی حکومتیں مسلّط ہوئیں اور ہوتی رہیںگی جو جس طرح چاہیں گی اُن سے معاملہ کریںگی اُن کا حکومت میں کوئی دخل نہ ہو گا.دوم بندر کا کام نقل کرنا ہوتا ہے.بندر کی عادت ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے ویسا ہی کرنے لگتا ہے اور بنی اسرائیل میں سے بھی ایک جماعت کے دل ایسے مسخ ہو گئے تھے کہ خشیت اﷲ کا نام نہ رہا تھا.ان کے تمام کام نقل کے طور پر تھے.حقیقت کچھ نہ تھی.چھلکے کو پکڑے بیٹھے تھے اور مغز سے بالکل بے خبر تھے حتّٰی کہ ایسا بھی کر لیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان بن جاتے اور ہم مذہبوں کے پاس جا کر یہودی بن جاتے.تیسرے بندروں میں شہوت زیادہ پائی جاتی ہے.عربی کا محاورہ ہے فُـلَانٌ اَ زْنٰی مِنْ قِرْدٍ (لسان و تاج) فلاں شخص بندر سے بھی زیادہ زنا کا رہے.یہود میں بھی بدکاری حد سے بڑھی ہوئی ہے حتّٰی کہ دنیا کے اکثر ملکوں میں یہودی زنانِ بازاری پائی جاتی ہیں.وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا اور (اس وقت کو بھی یاد کرو کہ) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے
Page 175
بَقَرَةً١ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا١ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ انہوں نے کہا کیاتو ہمیں تمسخر کا نشانہ بنا تا ہے (موسیٰ نے) کہا میں (اس بات سے )اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ( ایسا مِنَ الْجٰهِلِيْنَ۰۰۶۸ فعل کرکے) میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں.حَلّ لُغَات.ھُزُوًا.ھَزَأَ بِہٖ اور ھَزَأَ مِنْہُ کے معنے ہیں سَخِرَمِنْہُ اس سے تمسخر کیا (اقرب) ھُزُوًا اس کا مصدر ہے یعنی مسخری کرنا.مصدر بمعنے اسم مفعول استعمال ہوا ہے اور اَتَتَّخِذُ نَا ھُزُوًا کے معنے یہ ہیں کہ کیا تو ہمیں تمسخر کا نشانہ بناتا ہے.اَلْـجَاھِلِیْنَ.اَلْجَاھِلُوْنَ اور اَلْجَاھِلِیْنَ جَھَلَ سے اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے.اَلْجَھْلُ کے ایک معنی ہیں.فِعْلُ الشَّیْ ءِ بِخِلَافِ مَا حَقُّہٗ اَنْ یُّفْعَلَ کسی امر کو کما حقّہ ادا کرنے کے خلاف ادا کرنا.(مفردات) تفسیر.بنی اسرائیل چونکہ مصر میں رہتے تھے اور فرعونی لوگ گائے کی بہت عزت کرتے تھے اِس سبب سے اُن کے دل میں بھی گائے کی عظمت آ گئی تھی چنانچہ اِس سورۃ کی آیت ۵۲ اور خروج باب ۳۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے لئے ایک معبود بنایا تو وہ بچھڑے کی شکل پر ہی تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُن کے دل میں گائے کی عظمت اُلوہیت کی عظمت تک پہنچی ہوئی تھی اور چونکہ انبیاء کی اصل غرض دنیا سے شرک کا مٹانا اور اس واحد خدا کے جلال کا دنیا پر ظاہر کرنا ہوتا ہے جو سب مخلوق کا خالق اور مالک ہے اس لئے ضرور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کوئی ایسا سامان بھی کرتی جس سے بنی اسرائیل کے دل سے گائے کی وہ عظمت مٹ جائے جس کی وجہ سے وہ اس کی عبادت تک کے لئے تیار ہو جاتے تھے اور اگر ایسا بندوبست کوئی نہ کیا جاتا تو ضرور تھا کہ کچھ مدّت کے بعد بنی اسرائیل پھر گائے کی پرستش کی طرف متوجہ ہو جاتے.پس اِس فرض کو پورا کرنے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں گائے کی قربانی کا کئی جگہ حکم دیا گیا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک قوم ایک جانور کو ذبح کرتی رہے گی تو وہ کبھی اُسے اُلوہیت کی صفات سے متصف نہیں قرار دے سکتی.بنی اسرائیل کا مصری اثر کے ماتحت گائے کی تعظیم کرنا اور حضرت موسیٰ ؑکا اس عظمت کو مٹانے کے لئے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دینا مذکورہ بالا آیات میں بھی اسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک
Page 176
موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو گائے کی قربانی کا حکم دیا لیکن انہوں نے بہانہ بنا کر ٹالنا چاہا مگر آخر کار بادلِ نخواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے آگے سرِ تسلیم خم کرنا پڑا.اِس جگہ پر اﷲ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری کا ذکر کرتا ہے.گوسالہء سامری کے پوجنے کے بعد اور سخت سزاؤں کے برداشت کرنے کے بعد اور بڑی توبہ اور ندامت کے اظہار کے بعد یہ اُمید نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی وہی نسل پھر شرک کے قریب چلی جائے گی مگر انہوں نے اس واقعہ سے بھی عبرت حاصل نہ کی اور پھر شرک کی طرف راغب ہو گئے.معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بدقسمتی سے کوئی ایسا بَیل اُن کے گَلّے میں پیدا ہو گیا جو نہایت خوشنما اور خوش رنگ تھا.چونکہ فرعون کی قوم میں بَیل کی پوجا کا عام رواج تھا بلکہ سب سے بڑا مندر مصر کا وہی تھا جس میں ایک بے عیب بَیل بطور دیوتا کے رکھا جاتا تھا.انہوں نے اُس اثر کے ماتحت جو مصر میں رہنے کی وجہ سے اُن کے عقائد پر پڑا تھا.اُس بَیل کو خاص عزت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا.اس پر اﷲتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان میں گائے کی قربانی کا رواج پیدا کیا جائے تاکہ اس قسم کے خیالات کا قلع قمع ہو.بنی اسرائیل کے دل میں چونکہ چور تھا انہوں نے فوراً شبہ کیا کہ اس خاص بَیل کے متعلق جو ہماری قوم میں چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اُن کا پتہ لگ گیا ہے اور انہوں نے اُس بَیل کو مدّنظر رکھتے ہوئے ہمیں بَیل کی قربانی کا حکم دیا ہے.اُس وقت یہود کی مثال بالکل ’’چور کی داڑھی میں تنکا‘‘ والی ہو گئی اور انہوں نے بجائے اس کے کہ خاموشی سے ایک بَیل ذبح کر دیتے اور اس طرح اُن کے عیب پر بھی پردہ پڑا رہتا اور منشائے الٰہی بھی پورا ہو جاتا کہ آہستہ آہستہ اُن کے دلوں سے گائے اور بَیل کی عظمت بالکل نکل جائے اُلٹا یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوالوں کی بھرمار شروع کر دی کہ ضرور آپ کو اﷲ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص بَیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے اُس کی ہمیں نشانیاں بتائی جائیں.اس جرح قدح کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر اﷲ تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں جو اس مخصوص بَیل میں پائی جاتی تھیں جس کا ادب اور احترام بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہا تھا اُنہیں بتا دیںاور وہ خاص بَیل اُنہیں ذبح کرنا پڑا اور شرمندگی الگ اُٹھانی پڑی.مصری لوگوں میں بَیل کو پوجنے کا رواج مصری لوگوں میں بَیل کی عبادت اَور اُس کی عظمت کے متعلق تاریخ میں کثرت سے حوالے ملتے ہیں.نیوسٹینڈ رڈ ڈکشنری میں ایپس (APIS)کے لفظ کے نیچے لکھا ہے یہ ایک مقدّس بَیل ہوتا تھا جس کی مصری لوگ قدیم زمانہ میں پوجا کرتے تھے اور اپنے بُتوں اور تصویروں میں بھی اُس کی شکلیں دکھاتے تھے.وہ مصر کے مقدس جانوروں میں سے سب سے زیادہ اہم ہوتا تھا.اُس کی پیدائش کے دن کو
Page 177
موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو گائے کی قربانی کا حکم دیا لیکن انہوں نے بہانہ بنا کر ٹالنا چاہا مگر آخر کار بادلِ نخواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے آگے سرِ تسلیم خم کرنا پڑا.اِس جگہ پر اﷲ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک اور ناشکری کا ذکر کرتا ہے.گوسالہء سامری کے پوجنے کے بعد اور سخت سزاؤں کے برداشت کرنے کے بعد اور بڑی توبہ اور ندامت کے اظہار کے بعد یہ اُمید نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی وہی نسل پھر شرک کے قریب چلی جائے گی مگر انہوں نے اس واقعہ سے بھی عبرت حاصل نہ کی اور پھر شرک کی طرف راغب ہو گئے.معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بدقسمتی سے کوئی ایسا بَیل اُن کے گَلّے میں پیدا ہو گیا جو نہایت خوشنما اور خوش رنگ تھا.چونکہ فرعون کی قوم میں بَیل کی پوجا کا عام رواج تھا بلکہ سب سے بڑا مندر مصر کا وہی تھا جس میں ایک بے عیب بَیل بطور دیوتا کے رکھا جاتا تھا.انہوں نے اُس اثر کے ماتحت جو مصر میں رہنے کی وجہ سے اُن کے عقائد پر پڑا تھا.اُس بَیل کو خاص عزت کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا.اس پر اﷲتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان میں گائے کی قربانی کا رواج پیدا کیا جائے تاکہ اس قسم کے خیالات کا قلع قمع ہو.بنی اسرائیل کے دل میں چونکہ چور تھا انہوں نے فوراً شبہ کیا کہ اس خاص بَیل کے متعلق جو ہماری قوم میں چہ میگوئیاں ہو رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح اُن کا پتہ لگ گیا ہے اور انہوں نے اُس بَیل کو مدّنظر رکھتے ہوئے ہمیں بَیل کی قربانی کا حکم دیا ہے.اُس وقت یہود کی مثال بالکل ’’چور کی داڑھی میں تنکا‘‘ والی ہو گئی اور انہوں نے بجائے اس کے کہ خاموشی سے ایک بَیل ذبح کر دیتے اور اس طرح اُن کے عیب پر بھی پردہ پڑا رہتا اور منشائے الٰہی بھی پورا ہو جاتا کہ آہستہ آہستہ اُن کے دلوں سے گائے اور بَیل کی عظمت بالکل نکل جائے اُلٹا یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سوالوں کی بھرمار شروع کر دی کہ ضرور آپ کو اﷲ تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص بَیل کے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے اُس کی ہمیں نشانیاں بتائی جائیں.اس جرح قدح کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر اﷲ تعالیٰ نے وہ تمام علامتیں جو اس مخصوص بَیل میں پائی جاتی تھیں جس کا ادب اور احترام بنی اسرائیل میں پیدا ہو رہا تھا اُنہیں بتا دیںاور وہ خاص بَیل اُنہیں ذبح کرنا پڑا اور شرمندگی الگ اُٹھانی پڑی.مصری لوگوں میں بَیل کو پوجنے کا رواج مصری لوگوں میں بَیل کی عبادت اَور اُس کی عظمت کے متعلق تاریخ میں کثرت سے حوالے ملتے ہیں.نیوسٹینڈ رڈ ڈکشنری میں ایپس (APIS)کے لفظ کے نیچے لکھا ہے یہ ایک مقدّس بَیل ہوتا تھا جس کی مصری لوگ قدیم زمانہ میں پوجا کرتے تھے اور اپنے بُتوں اور تصویروں میں بھی اُس کی شکلیں دکھاتے تھے.وہ مصر کے مقدس جانوروں میں سے سب سے زیادہ اہم ہوتا تھا.اُس کی پیدائش کے دن کو ایک عام چھٹی کے طور پر مُلک میں منایا جاتا تھا اور اُس کی موت پر تمام ملک میں ماتم کیا جاتا تھا اور یہ ماتم اُس وقت تک جاری رکھا جاتا تھا جب تک ایک نیا ایپس اُن علامتوں کے مطابق جن سے اُس کے خدا کے مظہر ہونے کا ثبوت حاصل ہو نہ مل جائے.میمفِس (MEMPHIS)مقام پر اس کا بہت بڑا مندر تھا اور ہر ایسے بَیل کے مرنے کے بعد اس کی لاش میں مصالحے بھر دیئے جاتے تھے اور اُسے ایک چٹان سے کھو دے ہوئے مقبرہ میں دفن کر دیا جاتا تھا.انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈایتھکس(ENCYCLOPEDIA OF RELIGION AND ETHICS) صفحہ ۵۰۷ پر لکھا ہے کہ مصریوں میں جانور کی پوجاکرنے کا جو رواج تھا اس میں سب سے اہم مقام بَیل کو حاصل تھا.اور اس پوجا کا نشان بہت پُرانے زمانہ تک ملتا ہے.جب کوئی پُرانا ایپس یعنی بیل مر جاتا تھا تو ایک نئے بیل کی تلاش کی جاتی تھی اور جس گلے میں سے یہ بیل ملتا تھا اس کے مالک کو بڑی عزت دی جاتی تھی اور جو شخص اس کو تلاش کرتا تھا اُس کو بھی بہت بڑا انعام دیا جاتا تھا اور بَیل کی مادہ کو بھی لا کر میمفِس مندر کے ایک اور کمرہ میں رکھا جاتا تھا.سال میں صرف ایک دفعہ اُسے گائے سے ملنے کا موقع دیا جاتا تھا اور پھر اُس گائے کوقتل کر دیا جاتا تھا.اُس کی پیدائش کا دن ہر سال منایا جاتا تھا.اس دن اُسے پبلک کے سامنے لایا جاتا تھا.اور لوگ اُس کی زیارت کے لئے جمع ہوتے تھے.مصری لوگ اس بَیل کے احوال سے آئندہ کی خبریں معلوم کرتے تھے اور بیل کے مندر کے پجاریوں کی خوابوں سے ( بزعم خود) فائدہ اُٹھاتے تھے بلکہ اس مندر کے سامنے کھیلتے ہوئے بچّے جو باتیں کرتے تھے اُن سے بھی وہ پیشگوئیوں کا مفہوم نکالتے تھے.جب وہ مر جاتا تھا تو اُس کی ممی بنا کر ایک چٹان کی قبر میں محفوظ کر دیتے تھے.ایپس بَیل کی پوجا کسی خاص قبیلہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ سارا ملک اس کی عبادت کرتا تھا.اس بَیل کی پوجا کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ مصر کے دوسرے بادشاہ ’’ککاؤ‘‘ نامی نے شروع کی تھی اور میمفس پر اس کا مندر بنایا تھا اور اس بَیل کا نام سورج دیوتا کے باپ فتاح( PHTAH)دیوتا کے نام پر ایپس رکھا تھا.اسی طرح ہلیوپولس مقام پر اس نے ایک دوسرے بَیل منَیوِسMNEVIS نامی کی سورج دیوتا کی ایک زندہ یادگار کے طور پر پرستش کروانی شروع کی نیز ہر مان تھِس (HERMONTHIS)مقام پر ایک بَیل ’’باکھا‘‘ نامی کی پرستش شروع کرائی گئی جسے پہلے مَنتو (MENTUI) دیوتا کا اور بعد میں سورج دیوتا کا مظہر قرار دیا گیا.مصریوں میں بَیل کی طرح گائے کی بھی پوجا کی جاتی تھی.بیل کے سِوا اَور جانوروں کی پوجا بھی مصر میں ہوتی تھی اور جس قسم کے جانور کا نمائندہ کِسی مندر میں رکھا جاتا تھا.اُس قسم کے سارے جانوروں کو ہی مقدّس سمجھا جاتا تھا گو اُن کی پرستش نہیں کی جاتی تھی.اس قسم کے جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہوتا تھا.اور اگر کوئی شخص کسی دیوتا کے
Page 178
ہم قسم جانور کو مار دیتا تھا تو جان بوجھ کر مارنے کی صورت میں اُس کو قتل کی سزا ملتی تھی اور نادانستہ مارنے کی صورت میں جرمانہ ہوتا تھا.میمفِس کے دیوتا بیلوں کا سِلسِلہ مصریوں کے آخری بادشاہوں تک چلنا ثابت ہے چنانچہ رعمسیس ثانی کے زمانہ سے لے کر جس کے زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اُس کے ٹولو مک زمانہ PTOLEMAIC PERIODتک کم سے کم چوبیس بَیل یکے بعد دیگرے میمفِس کے مقام پر فتاح کے مندر میں پوجا کے لئے رکھے گئے تھے.(دی نائل اینڈ ایجپشن سیویلائزیشن THE NILE AND EXYPTIAN CIVILIZATION BY MORET edition 1927 page 264.265 مصنّفہ اے مارٹ پروفیسر فرانس یونیورسٹی ( مصری لوگوں کا اپنی عبادت گاہ میں خاص قسم کے بیل کو تلاش کر کے رکھنا ان حوالجات سے ثابت ہوتا ہے کہ مصر میں بیل کی پوجا خاص طور پر کی جاتی تھی اور خاص علامتوں والے بیل اس غرض کے لئے چُنے جاتے تھے.معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل نے بھی مصر میں رہنے کی وجہ سے مصریوں کے اس خیال کے اثر کو قبول کر لیا تھا.جب اتفاقاً اُن کی قوم کے کسی گلّہ میں ایک غیر معمولی طور پر خوبصورت بَیل پیدا ہو گیا تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال کر لیا کہ سورج دیوتا نے ان پر بھی نظر ڈالی ہے اور اُن کی قوم کے ایک بیل میں جنم لیا ہے.اﷲ تعالیٰ نے اُن کے اس شرک کو دُور کرنے کے لئے بیل اور گائے کی قربانی کا حکم دیا.لفظ بَقَرَة میں بَیل اور گائے ہر دو مراد لئے جا سکتے ہیں ( قرآن کریم میں بَقَرَة کا لفظ ہے جو بیل اور گائے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے.ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر بقرة کو مؤنث سمجھ کر گائے کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے مگر یہ لفظ صرف مؤنث پر دلالت نہیں کرتا بلکہ خواہ نر ہو یا مادہ دونوں کو بقرة کہتے ہیں) بائبل میں اس تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کا ذکر نہیں آتا جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اور مَیں یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ بائبل میں کسی تاریخی واقعہ کا ہونا یا نہ ہونا ایک محفوظ الہامی کتاب کے بیان کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا مگر پھر بھی بائبل میں ایک اسی قسم کے بیل کی قربانی کا حکم جس کی علامات قرآن کریم نے بتائی ہیں ضرور پایا جاتا ہے.بائبل میں لکھا ہے.’’ بنی اسرائیل کو کہہ کہ ایک لال گائے جو بے داغ اور بے عیب ہو اور جس پر کبھی جؤا نہ رکھا گیا ہو تجھ پاس لاویں تم اسے الیعزر کاہن کو دو کہ اُسے خیمہ گاہ سے باہر لے جاوے اور وہ اُس کے حضور ذبح کی جاوے اورالیعزر کاہن اپنی اُنگلی پر اُس کا لہو لیوے اور جماعت کے خیمے کے آگے کی طرف اُس کے لہو کو سات مرتبہ چھڑ کے پھر اُس کی آنکھوں کے سامنے وہ گائے جلائی جاوے.اس کا چمڑا، اُس کا گوشت ، اس کا خون ، اس کے گوبر سمیت سب جلایا جاوے پھر کاہن وہاں
Page 179
دیودار کی لکڑی اور زوفا اور قرمزلے کے اس جلتی ہوئی گائے پر ڈال دے.تب کاہن اپنے کپڑے دھووے اور اپنا بدن پانی سے دھووے بعد اس کے خیمہ گاہ میں داخل ہو اور کاہن شام تک ناپاک رہے گا اور وہ جو اُسے جلاتا ہے اپنے کپڑے پانی سے دھووے اور اپنا بدن پانی سے دھووے اور شام تک ناپاک رہے گا اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو جمع کرے اور خیمہ گاہ کے باہر صاف جگہ دھردے.یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لئے محفوظ رہے گی تاکہ جدائی کے پانی میں ملائی جاوے.یہ گناہ سے پاک کرنے کے لئے ہے.‘‘ (گنتی باب ۱۹آیت ۲ تا ۹) گو اس حوالہ میں ان سوالات و جوابات کا ذکر نہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں پھر بھی ایک ادنیٰ نظر سے یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ گو بائبل نے اسے ایک عام واقعہ کے طور پر بیان کیا ہے لیکن اصل حکمت اس قسم کی گائے کے ذبح کرنے میں یہی تھی کہ بنی اسرائیل کے دل سے شرک کو مٹایا جائے اور اُن کو غیر قوموں کے اثر سے محفوظ کیا جائے اور شائد اسی حکمت کی وجہ سے اُس پانی کا نام جس میں گائے کی راکھ کو ملانے کا حکم تھا جدائی کا پانی رکھا گیا.یہ جو بائبل میں آتا ہے کہ ’’ یہ گناہ سے پاک کرنے کے لئے ہے.‘‘ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر تم اس قسم کے بَیل یا گائے جن کی مصر میں پوجاکی جاتی تھی بار بار قربان کرو گے تو تبھی تمہارے دل شرک سے پاک ہوں گے.بائبل کا جو حوالہ نقل کیا گیا ہے یہودی احادیث کی کتابوں میں اس سے بڑھ کر اس گائے کی تفاصیل دی گئی ہیں چنانچہ مِثنا ( یہودی حدیثوں کی کتاب) میں اس گائے کے متعلق نہایت تفصیلی بحثیں کی گئی ہیں اور ایک باب کا باب اس کے لئے وقف کر دیا گیا ہے.رِبّینسیس کی روایت اس کے متعلق یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بعد پھر ان شرطوں والی گائے کوئی نہیں ملی ( انسائیکلو پیڈیا ببلیکا زیر لفظ Clean and Unclean Holy and Profane)یہودی کتبِ احادیث کا یہ بیان قرآن کریم کی اِس بارہ میں کامل تصدیق کر دیتا ہے کہ درحقیقت ایک خاص گائے کو اُس وقت ذبح کرانا مقصود تھا جس میں بعض غیر معمولی قسم کی خوبصورتی کے نشانات پائے جاتے تھے اور اس قسم کی گائے عام طور پر ہر زمانہ میں نہیں ملتی.قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ....الخ میں اس طرف اشارہ کہ دینی امور میں تمسخر نہیں کرنا چاہیے قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دینی امور میں ہنسی اور تمسخر کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے.افسوس بہت سے لوگ اس امرکی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دینی امور میں ہنسی اور مذاق کر کے یا عدم سنجیدگی کا اظہار کر کے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں.
Page 180
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ١ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ انہوں نے کہا ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ (گائے) کیسی ہے.اس نے( یعنی اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ١ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ١ؕ موسیٰ ؑنے )کہا کہ وہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے کہ نہ تو وہ بڑھیا ہے اور نہ بچھیا (بلکہ )پوری جوان ہے.اس( بیان فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ۰۰۶۹ کردہ حد بندی )کے درمیان کی ہے اس لئے جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاؤ.حَلّ لُغَات.فَارِضٌ.فَرُضَ سے ہے اور فَرُضَتِ الْبَقَرَۃُ کے معنے ہیں کَبُرَتْ وَ طَعَنَتْ فِی السِّنِ کہ گائے بوڑھی ہو گئی اور لَافَارِضٌ وَّ لَابِکْرٌ کے معنے ہیں لَا مُسِنَّۃٌ وَلَا فَتِیَّۃٌ نہ بُڑھیا اور عمر رسیدہ ہے اور نہ بچھیا.(اقرب) بِکْرٌ.اَلْبَقَرَۃُ الْفَتِیَّۃُ.نو عمر گائے ( اقرب) بِکْرٌ فِیْ قَوْلِہٖ تَعَالٰی لَافَارِضٌ وَّ لَابِکْرٌ ھِیَ الَّتِیْ لَمْ تَلِدْ یعنی لفظ بِکْرٌ جو آیت لَافَارِضٌ وَّلَابِکْرٌ میں گائے کی صفت میں استعمال ہوا ہے اس کے معنے ہیں ایسی گائے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو.(مفردات) عَوَانٌ.اَلنَّصَفُ درمیانی عمر کی.پوری جوان.(اقرب) تفسیر.تفصیل کے لئے دیکھو اوپر کی آیت کا نوٹ.عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَکی تشریح پہلی آیت میں صرف ایک بیل یا گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا مگر چونکہ یہودیوں کے دل میں چور تھا انہوں نے علامتیں پوچھنی شروع کر دیں.اﷲ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو وہ گائے یا بیل فَارِضٌ یعنی بوڑھا ہو اور نہ بِکْـرٌ یعنی بچہ ہو بلکہ عَوَانٌ یعنی جوان ہو.بَیْنَ ذٰلِکَ کے لفظی معنے تو یہ ہیں کہ اس کے درمیان اور درمیان کا لفظ ایک چیز پر نہیں بولا جاتا بلکہ دو۲ یا دو۲ سے زیادہ چیزوں پر بولا جاتا ہے.پس یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ’’ اس کے درمیان‘‘ سے کیا مراد ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہاں ذٰلِکَ سے مراد فَارِضٌ اور بِکْرٌ کا مجموعہ ہے یعنی مراد یہ ہے کہ اس تفصیل کے درمیان درمیان.یا یہ کہ ایک ذٰلِکَ محذوف ہے اور مراد یہ ہے کہ بَیْنَ ذٰلِکَ وَذٰلِکَ.
Page 181
فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ کہہ کر حکم دیا کہ اب زیادہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو جس طرح کہا جاتا ہے کرو.شرطیں نہ پُوچھو لیکن یہود پھر بھی باز نہ آئے اور جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہے انہوں نے پھر اور سوال کر دیا.قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا١ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ انہوں نے کہا ہماری خاطر اپنے رب سے (پھر )دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے (موسیٰ ؑنے )کہا وہ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ١ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ۰۰۷۰ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے اس کا رنگ بہت شوخ ہے (اور) وہ دیکھنے والوں کو بہت پسند آتی ہے.حَلّ لُغَات.صَفْرَآءُ فَاقِعٌ.فَقَعَ لَوْنُہٗ کے معنے ہیں اِشْتَدَّ تْ صُفْرَتُہٗ.اس کا رنگ بہت زرد تھا اَلْفَاقِعُ.اَلْخَالِصُ الصُّفْرَۃِ خالص زردی والا رنگ.اَلْخَالِصُ الصَّافِیْ مِنَ الْاَلْوَانِ اَیُّ لَوْنٍ کَانَ خالص اور صاف رنگ خواہ کوئی ہو.وَالْمَشْھُوْرُ اَنَّہٗ صِفَۃٌ لِلْاَصْفَرِ اور لفظ فَاقِعٌ زرد رنگ کے لئے بطور صفت کے آتا ہے یعنی جب اَصْفَرُ کے لئے لفظ فَاقِعٌ استعمال کریں گے تو معنے ہوں گے شوخ زرد رنگ.(اقرب) تفسیر.انہوں نے پہلے سوالوں پر بس نہ کی بلکہ باوجود الٰہی اشارہ کے کہ ہم تو تمہاری پردہ پوشی کر رہے ہیں تم زیادہ سوال نہ کرو.پھر یہ سوال کر دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو.پس اس کا جواب دیا کہ اُس کا رنگ زرد فَاقِعٌ ہو.عربی زبان میں ہر رنگ کے لئے الگ الگ خصوصیّت آتی ہے.سَوْدَاءُ سیاہ کو کہتے ہیں لیکن اگر بہت سیاہ مراد ہو تو اس کے لئے حَالِکٌ کی صفت استعمال کرتے ہیں.اسی طرح صَفْرَآءُ کا لفظ زرد رنگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر نہایت خوبصورت اور گہرا زرد مراد ہو تو اس کے لئے فَاقِعٌ کی صفت استعمال کرتے ہیں.قربانی کی جانے والی گائے کا رنگ بیان کرنے میں بائبل اور قرآن مجید کا اختلاف اور اصل حقیقت بائبل میں اس کے لئے سرُخ گائے کا لفظ آیا ہے لیکن قرآن کریم نے اس کے لئے صَفْرَآءُ کا لفظ استعمال کیا ہے.بعض لوگ اس میں بھی اختلاف قرار دیتے ہیں گو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں قرآن کریم جیسی محفوظ الہامی کتاب کو اگر بائبل سے اختلاف ہو تو اِس میں کوئی تعجب کی بات نہیں.وہ غیر محفوظ ہے اور یہ محفوظ ہے لیکن یہ اختلاف میرے نزدیک کوئی اختلاف نہیں کیونکہ بعض رنگ باہم مشابہ ہوتے ہیں اور مختلف نقطۂ نگہ سے ان پرمختلف الفاظ بول لئے جاتے ہیں.گہرا زرد رنگ بھی ایسے ہی رنگوں میں سے ہے.کوئی دیکھنے والا اسے زرد قرار دے دیتا
Page 182
ہے اور کوئی سرُخ جیسے زعفران ہے.زعفران اگر مختلف لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو بعض لوگ اس کا رنگ سُرخ بتائیں گے اور بعض اس کا زرد رنگ قرار دیں گے جس رنگ کی وہ گائے تھی.معلوم ہوتا ہے یہودی لوگ اس کو سُرخ کہا کرتے تھے اور عرب کے لوگ اسے زرد کہتے تھے.قرآن آخر عربی میں اُترا ہے اور اُس نے عربی کے محاورہ کو ہی استعمال کرنا تھا پس یہ حقیقی اختلاف نہیں بلکہ ایک ہی بات کو مختلف طریق سے بیان کرنے کی ایک مثال ہے.تَسُرُّ النّٰظِرِیْنَ میںلفظتَسُرُّ کی ضمیر کا مرجع تَسُرُّ کا صیغہ مؤنث آیا ہے حالانکہ تَسُرُّ کی ضمیر لَوْنٌ کی طرف جاتی ہے جو مذکّر ہے.لَون کو مدِّنظر رکھتے ہوئے یہاں یَسُرُّ چاہیے تھا نہ کہ تَسُرُّ.اِس اشکال کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کا یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی لفظ کسی دوسرے لفظ کی طرف مضاف ہو تو خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث.مضاف الیہ کے مطابق اُس کی طرف ضمیر پھیرنی بھی جائز ہوتی ہے.فرض کرو مضاف مذکر ہے اور مضاف الیہ مؤنث ہے تو یہ جائز ہو گا کہ باوجود مضاف کے مذکر ہونے کے اس کی طرف مؤنث کی ضمیر پھیر دی جائے.چونکہ لَوْن.ھا کی طرف جو مؤنث کی ضمیر ہے مضاف ہوا تھا اس لئے باوجود اس کے مذکر ہونے کے ھَا کو مدّنظر رکھتے ہوئے تَسُرُّ میں مؤنث کی ضمیر استعمال کی گئی.دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی عربی زبان میں ضمیر بالمعنیٰ بھی پھیر دی جاتی ہے چونکہ لَوْن سے مراد صُفْرَۃٌ تھی ( یعنی زردرنگ) جو مؤنث ہے اِس لئے مؤنث کی ضمیر پھیر دی گئی.تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے.تَسُرُّ کی ضمیر لَوْنکی طرف نہیں بلکہ بَقَرَة کی طرف جاتی ہے.تَسُرُّالنّٰظِرِیْنَ بَقَرة کی دوسری صفت ہو.مطلب یہ کہ وہ بَیل زرد بھی ہے اور ایسا خوبصورت بھی ہے کہ دیکھنے والوں کو پسند آتا ہے.قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ١ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنے رب سے (پھر )دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ( گائے) کیسی ہے.ہمیں تو عَلَيْنَا١ؕ وَ اِنَّاۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ۰۰۷۱ اس قسم کی( سب) گائیں ایک ہی جیسی نظر آتی ہیں اور( یقین رکھیے کہ) اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت کوقبول کر لیں گے.حَلّ لُغَات.تَشَا بَہَ.اَلرَّجُلَانِ کے معنے ہیں اَشْبَہَ کُلٌّ مِّنْہُمَاالْاٰخَرَحَتَّی الْتَبَسَا کہ دو شخص اس
Page 183
طور پر ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے کہ ان کا پہچاننا مشکل ہو گیا.(اقرب) تفسیر.پھر بھی وہ لوگ سوال سے باز نہ آئے اور کہا ہمیں کچھ اور شرطیں بتاؤ مگر دل میں چونکہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اس جگہ پر بَیل کی قربانی سے مراد اُس خاص بَیل کی قربانی ہے جو ہماری قوم میں معزز سمجھا جاتا ہے.اس لئے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اگر یہی حکم ہوا تو ہم اسے ذبح کر ہی دیںگے پس ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا.وَ اِنَّ اِنْشَآءَ اللہُ لَمُھْتَدُوْنَ.کہ خدا نے چاہا تو جو بَیل بھی آپ کہیں گے ہم اسے قربان کر دیں گے.قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَ لَا (موسیٰ ؑ نے )کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے نہ تو جوئے کے نیچے لائے گئی ہے کہ ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی تَسْقِي الْحَرْثَ١ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا١ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ دیتی ہے.بالکل تندرست ہے اس میں کوئی غیر رنگ نہیں( پایا جاتا )انہوں نے کہا (ہاں) اب تو نے( ہم پر) جِئْتَ بِالْحَقِّ١ؕ فَذَبَحُوْهَا وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَؒ۰۰۷۲ حقیقت کھول دی ہے چنانچہ انہوں نے اس( گائے) کو ذبح کر دیا.گو وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہ تھے.حَلّ لُغَات.مُسَلَّمَۃٌ.سَلَّمَ سے اسم مفعول مُسَلَّمٌ آتا ہے.مُسَلَّمَۃٌ مُسَلَّمٌ کا مؤنث کا صیغہ ہے.سَلَّمَہُ اللہُ مِنَ الْاٰفَۃِ کے معنے ہیں وَقَاہُ اِیَّاھَا کہ اﷲ تعالیٰ نے فلاں شخص کو بیماریوں، تکالیف اور خرابیوں وغیرہ کی آفات سے محفوظ رکھا.(اقرب) پس مُسَلَّمَۃٌ کے معنے ہوں گے تندرست.جملہ بیماریوں اور خرابیوں سے محفوظ اور بچی ہوئی.شِیَۃٌ.وَ شَیْتُ الشَّیْءَ وَشْیًا کے معنے ہیں جَعَلْتُ فِیْہِ اَثَرًا یُخَالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِہٖ.مَیں نے کسی چیز میں ایسا نشان کر دیا جو اس کے اصل رنگ کے مخالف تھا (مفردات) شِیَۃٌ.کُلُّ لَوْنٍ یُخَالِفُ مُعْظَمَ لَوْنِ الْفَرَسِ وَغَیْرِہٖ یعنی گھوڑے یا کسی اور جانور کے بدن کے اکثر رنگ کے خلاف جو اس کے بدن میں تھوڑا سا رنگ ہو.اس کو شِیَۃٌ کہتے ہیں ( مثلاً کسی جانور کے بدن کا سارا رنگ سفید ہے.اس میں قدرے کہیں سیاہی آ جائے یا سارا رنگ سیاہ ہے اور کہیں سفیدی آ جائے ) شِیَۃٌ کی جمع شِیَاتٌ آتی ہے (اقرب) پس لَاشِیَۃَ فِیْہَا کے معنے
Page 184
ہوں گے.اس کا رنگ ایک جیسا ہے اور کوئی غیر رنگ اس میں نہیں پایا جاتا.تفسیر.آخر اﷲ تعالیٰ نے وہ ساری علامتیں بیان کر دیں جس سے اس مخصوص بَیل کی تعیین ہو گئی.فرمایا نہ تو وہ زمین میں جوتا ہوا ہو، نہ اس سے پانی لیا جاتا ہو مطلب یہ کہ سانڈ کے طور پر چھوڑا ہوا ہے تم اُس کے اعزاز کی وجہ سے اُس سے کِسی قسم کا کام نہیں لیتے اور وہ ایک بے عیب بَیل ہے کہ نہ کوئی اس کو مارتا ہے نہ پیٹتا ہے اور اس وجہ سے کہ اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں پڑتے.گویا جو اُن بیلوں کا حال ہوتا ہے جن کا لوگ مذہبی طور پر اعزاز کرتے ہیں وہی اس کا حال ہے.اس طرح تمام علامتیں خدا تعالیٰ نے بتا دیں اور یہود نے بھی آخر کہہ دیا کہ آپ نے ہمیں سچ سچ بات آخر بتا ہی دی یعنی ہم پہلے سے سمجھتے تھے کہ فلاں بَیل کی قربانی کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بات تو پہلے بھی سچی ہی تھی.اﷲ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ وہ شرمندہ نہ ہوں اور گائے کی قربانی اُن میں شروع ہو جائے.آہستہ آہستہ اِس قسم کا شرک بھی دل سے نکل جائے گا.انہوں نے خود اصرار کر کے اس بَیل کی تعیین کرائی اور پھر یہ لاف زنی کرنے لگ گئے کہ اب آپ نے سچ بات بیان کی ہے پھر آگے فرمایا آخر انہوں نے اُس گائے یا بیل کو ذبح کر ہی دیا مگر کچھ خوش دلی سے نہ کیا.یہود کا یہ فقرہ کہ اب آپ نے اصلی بات بتائی ہے کتنا واضح ثبوت اس امر کا ہے کہ ان کے اندر کسی خاص بیل کی نسبت مشرکانہ خیال پیدا ہو چکے تھے ورنہ اُن کا گائے کی قربانی کا حکم ملنے پر سوال پر سوال کرنا اور آخر بعض تفصیلی علامات کے بتائے جانے پرکہنا کہ اب آپ نے اصلی بات بتا دی ہے کس طرح ممکن تھا.عیدالاضحیہ پر قربانی کے لئے بَیل لانے کے لئے ہمیشہ امراء اپنے ملازموں کو حکم دیتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ ہم سمجھے نہیں کیسی گائے اور نہ سوال پر سوال کر کے خاص قسم کی گائے کو مخصوص کراتے ہیں.اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گائے سے مراد گائے سمجھتے ہیں نہ خاص قسم کی گائے.لیکن یہودیوں کے دل میں چونکہ ایک خاص بیل کی نسبت مشرکانہ عقیدہ گھر کر چکا تھا انہوں نے شروع سے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہو نہ ہو اس عام حکم کے نیچے اس خاص بَیل کی قربانی کا حکم مخفی ہے پس وہ جرح کرتے گئے کرتے گئے یہاں تک کہ خاص اسی بَیل کا حُلیہ اُنہیں بتا دیا گیا جسے وہ خدا تعالیٰ کا مظہر سمجھ رہے تھے.موسیٰ علیہ السلام کی غَیبت میں بنی اسرائیل کا بچھڑے کی پوجا کرنا اس امر کا ثبوت ہے کہ یہود کا عقیدہ گائے کے متعلق مشرکانہ تھا موسیٰ ؑ کی غَیبت میں بنی اسرائیل کا بچھڑے کی پوجا کرنا اس امر کا مزید ثبوت ہے کہ یہود کا عقیدہ گائے کی نسبت مشرکانہ تھا.تاریخ سے ثابت ہے کہ مصریوں میں زندہ بیل کی بھی اور اُس کے بُت کی بھی پوجا کی جاتی تھی.پس ایک دفعہ انہوں نے بُت کی اور دوسری دفعہ زندہ بَیل کی پوجا کی کوشش کی.بیل
Page 185
کا جو رنگ بتایا گیا ہے وہ بھی اس امرکا ثبوت ہے کیونکہ بچھڑے کا بُت بھی انہوں نے سونے کا بنایا تھا جو زرد ہوتا ہے اوروہ بَیل جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا رنگ بھی زرد بتایا گیا ہے چنانچہ عربی زبان میں صَفْرَاءُ کے لفظ کے معنے جو لفظ کہ بَیل کے رنگ کے بتانے کے لئے قرآن کریم نے استعمال کیا ہے ذَھَبٌ.یعنی سونے کے بھی ہیں.(اقرب) پس بُت سونے سے تیار کرنا اور قربانی کے رنگ کا صَفْرَآءُ بتایا جانا بتاتا ہے کہ جس قسم کے بَیل کو یہود خدائی صفات سے متّصف سمجھتے تھے وہ سنہری رنگ کا ہوتا تھا.بَیل کو سورج دیوتا کا مظہر قرار دے کر اس کی عبادت کرنے کا رواج اس امر کا ایک اَور زبردست قیاسی ثبوت بھی ہے کہ یہ بَیل جس کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا درحقیقت یہود کا مرکز عبادت بن رہا تھا یا بننے والا تھا اور وہ یہ کہ اس کا رنگ زرد بتایا گیا ہے اور جیسا کہ مَیں اوپر مصری تاریخوں کے حوالوںسے ثابت کر آیا ہوں بَیل جس جس مندر میں اُلوہیت کے مقام پر کھڑا کیا گیا تھا سُورج دیوتا کا مظہر قرار دے کر اسے پوجا گیا تھا.ممفس میں اس کی پوجا فتاح کے نام پر کی جاتی تھی جو ’’رَا‘‘ یعنی سورج دیوتا کا باپ کہا جاتا تھا اور ہیلیوپولس اور ہرمانتھس دونوں مندروں میں اسے سُورج دیوتا کا مظہر بتایا جاتا ہے.چونکہ سورج کا رنگ بھی سنہری ہوتا ہے اس لئے یہ امر کہ وہ بَیل گہرے زرد رنگ کا تھا اس بات پر زبردست دلالت کرتا ہے کہ یہود نے اسے سُورج دیوتا کا مظہر سمجھا تھا.اس قیاس کی درستی کو اگر تسلیم کیا جائے تو بَیل کے رنگ کے متعلق جو دو مختلف الفاظ بائبل اور قرآن کریم میں استعمال کئے گئے ہیں ان کے بارہ میں بھی یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے جو اس کی نسبت زرد کا لفظ استعمال کیا ہے وہ واقعات کے لحاظ سے زیادہ موزون ہے بہ نسبت سرخ کے لفظ کے جسے بائبل نے استعمال کیا ہے.وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے یعنی اس بَیل کا ذبح کرنا اُن کے دل پر بہت گراں گزرا کیونکہ مصری اثر کے ماتحت وہ سمجھتے تھے کہ اس بَیل میں کچھ نہ کچھ خدائی ضرور ہے.اﷲتعالیٰ کے احکام کیسے پُر حکمت ہوتے ہیں.اﷲ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بھی گائے کی قربانی کو رائج کر کے اس شرک کو ملیامیٹ کر دیا ہے جو دنیا میں آج بھی گائے کے متعلق پایا جاتا ہے گو افسوس کہ بغیر کسی دینی فائدہ کے مسلمان اِس حق کو چھوڑنے کے لئے آمادہ نظر آتے ہیں اور یا پھر خواہ مخواہ قربانی کی گائیوں اور بیلوں کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمسایہ قوموں کے دلوں کو دکھاتے ہیں.یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں.مومن کا کام اپنی اصلاح ہے.ہمسایہ کو دُکھ دینا اس کے لئے جائز نہیں ہوتا.بانی ٔ سِلسِلہ احمدیہ علیہ الصَّلٰوة وَالسَّلام نے کیا منصفانہ طریق اپنی ہمسایہ قوموں کے لئے پیش کیا.وہ
Page 186
اپنی کتاب ’’ پیغام صلح‘‘ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ’ ’ ہم ہندوؤں کے بزرگوں حضرت کرشن اور حضرت رامچندر جی کو قرآنی تعلیم کے مطابق خدا تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں اگر ہندو لوگ بھی ہمارے آنحضرت صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی اسی طرح عزّت کرنے لگ جائیں تو ہم ان کی اِس قربانی کے بدلہ میں اِس بات کے لئے تیار ہیں کہ اِس مُلک میں گائے کی قربانی کو بند کر دیں.‘‘مگر افسوس کہ ہندو قوم نے اس نہایت ہی منصفانہ پیشکش کو قبول نہ کیا.وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا١ؕ وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو) جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم میںسے ہر ایک نے اپنے سر سے الزام کو دور کرنے تَكْتُمُوْنَۚ۰۰۷۳ کی کوشش کی حالانکہ جو( کچھ) تم چھپاتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا.حَلّ لُغَات.قَتَلْتُمْ.قَتَلَ سے جمع مخاطب کا صیغہ ہے.تشریح کے لئے ملاحظہ کریں حَلِّ لُغَات سورہ ھٰذا آیت نمبر ۵۵ اور ۶۲.نَفْسًا.نَفْسٌ کی تشریح کے لئے دیکھو حَلِّ لُغَات سورہ ھٰذاآیت نمبر۴۹.فَادّٰرَءْ تُمْ.اِدّٰرَءْ تُمْ اصل میں تَدَارَءْ تُمْ تھا.’’ تا ‘‘ اور ’’د‘‘ جو کہ قریب المخارج ہیں اکٹھے آ گئے پس ’’تا‘‘ ’’دال ‘‘ ہو کر دال میں مدغم کر دی گئی.ادغام کی وجہ سے ابتدائی حرف ساکن ہو گیا اور اس وجہ سے اس کا پڑھا جانا ناممکن تھا اس لئے اس کے قبل ہمزہ وصل لگایا گیا تاکہ ابتداء کا حرف پڑھا جا سکے.تَدَارَءْ تُمْ دَرَءَ سے باب تفاعل کا ماضی جمع مخاطب کا صیغہ ہے دَرَءَ ہٗ (یَدْرَءُ ہٗ) کے معنی ہیں دَفَعَہٗ وَقِیْلَ دَفَعَہٗ ( دَفْعًا) شَدِیْدًا یعنی کسی کو اپنی طرف سے ہٹایا یا سختی سے دُور کر کے اپنا بچاؤ کیا.اور تَدَارَءَ الْقَوْمُ کے معنے ہیں تَدَافَعُوْافِی الْـخُصُوْمَۃِ وَاخْتَلَفُوْا یعنی لوگوں نے آپس میں سختی سے جھگڑا کیا اور ہر ایک نے دوسرے کو ملزم کر کے اپنا بچاؤ کرنا چاہا اور اس طرح ان کے درمیان اختلاف برپا ہو گیا.اَلدَّرْءُ ( جو دَرَءَ کا اسم مصدر ہے ) کے اصل معنے اَلْمَیْلُ وَالْعِوَجُ فِی الْقَنَاۃِ کے ہیں یعنی نیزہ میں ٹیڑھاپن اور کجی کا ہونا.عرب کہتے ہیں قَوَّمْتُ دَرَءَ فُـلَانٍ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ مَیں نے فلاں شخص کی کجی اور غلط رَوِی کو دُور کیا نیز اس کے معنے ہیں اَلْخِلَافُ جھگڑا.اختلاف (اقرب) زجّاج کہتے ہیں مَعْنَی اِدّٰرَءْ تُمْ فَتَدَارَءْ تُمْ اَیْ تَدَافَعْتُمْ اَیْ اَلْقٰی بَعْضُکُمْ اِلٰی بَعْضٍ کہ اِدّٰرَءْ تُمْ کے معنے ہیں تم نے
Page 187
آپس میں کسی امر کے متعلق اس طور پر اختلاف کیا کہ ہر ایک نے اپنے سر سے الزام کو دُور کرنے اور دوسرے کے ذمّہ لگانے کی کوشش کی.(لسان) مُـخْرِجٌ.اَخْرَجَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اَخْرَجَ الشَّیْءَ کے معنے ہیں اَبْرَزَہٗ کسی چیز کو ظاہر کیا.نکالا.(اقرب) پس مُخرِجٌ کے معنے ہوں گے ظاہر کرنے والا.تَکْتُمُوْنَ.کُنْتُمْ تَکْتُمُوْنَ کے معنی ہیں تم چھپاتے تھے.تَکْتُمُوْنَ کَتَمَ (یَکْتُمُ کَتْمًا وَ کِتْمَانًا) سے مضارع جمع مخاطب کا صیغہ ہے کَتَمَ الشَّیْءَ کے معنی ہیں اَخْفَاہُ اس کو پوشیدہ رکھا.بعض اوقات کَتَمَ کے دو مفعول آ جاتے ہیں چنانچہ کہتے ہیںکَتَمَ زَیْدَنِ الْحَدِیْثَ کہ اس نے زید سے بات کو مخفی رکھا.اس میں زَیْد اور اَلْحَدِیْثَ دونوں کَتَمَ کے مفعول ہیں (اقرب) نیز اہل عرب کہتے ہیں کَتَمَ الْفَرَسُ الرَّبْوَ اور اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ضَاقَ مَنْخِرُہٗ عَنْ نَفْسِہٖ کہ گھوڑا جب دوڑتے ہوئے ہانپ گیا اور لمبے سانس لینے لگا تو نتھنوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح سانس نہ لے سکا (اقرب)گویا جب کسی چیز کی وضع ایسی ہو کہ وہ کسی بات کے ظاہر کرنے سے قاصر ہو تو اس وقت بھی اس کے متعلق کَتَمَ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں.مفرداتِ راغب میں امام راغب لکھتے ہیں کہ لَا یَکْتُمُوْنَ اللّٰہَ حَدِیْثًا کے معنی حضرت ابن عباسؓ اور حسنؓ نے یہ کئے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکنا اس طور پر ہو گا کہ اُن کے جوارح تمام باتو ںکو ظاہر کر دیںگے.(مفردات) گویا آپ ہی آپ جو بات ظاہر ہو جائے وہ خلاف کَتَمَ ہے.پس جو بات آپ ہی رکی ہوئی ہو اس پر کَتَمَ بولیں گے.پس تَکْتُمُوْنَکے دو معنے ہوئے (۱) جو تم چھپاتے ہو (۲) جو تم سے ظاہر نہیں ہو سکتا.جو چیز باہر آنی تھی وہ بسبب ناقابلیت کے نہیں آ سکتی یعنی تمہاری خلقت ایسی ہے کہ تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا.تفسیر.اِدّٰرَءْ تُمْ کی تشریح اِدّٰرَءْ تُمْ کے معنے اختلاف کرنے اور ایک دوسرے پر الزام لگانے کے ہوتے ہیں.پس مطلب یہ ہے کہ یاد کرو.جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا اور پھر اُس میں اختلاف سے کام لیا.کسی نے کہا فلاں شخص نے اس کو مارا ہے.کسی نے کہا فلاں شخص نے مارا ہے یا یہ کہا کہ ہم نے نہیں مارا کسی اور نے مارا ہو گا یا یہ کہ اُس کے قتل کے بارہ میں کسی اور قسم کا کوئی اختلاف کیا یہ سب معنے اس آیت پر چسپاں ہو سکتے ہیں کیونکہ اِدَّارَءَ کے لفظ میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں.قَتَلْتُمْ نَفْسًا کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کرنے والی یہودی قوم تھی یا یہودی قوم قاتل کی پشت پر تھی تبھی فرمایا گیا کہ تم یہودیوں نے قتل کیا.اگر یہ کوئی انفرادی واقعہ ہوتا تو پھر قوم کی طرف قتل کا فعل منسوب نہ کیا جاتا.قتل
Page 188
کے معنے اس جگہ پر ارادۂ قتل کے بھی ہو سکتے ہیں.( دیکھئے تفسیر آیت نمبر ۶۲) وَاِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًامیں نَفسکو نکرہ استعمال کرنے کی وجہ نَفْسًا پر جو تنوین آئی ہے اس کے معنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی غیر معروف آدمی کو اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک عظیم الشّان انسان کو قتل کیا.کیونکہ تنوین عربی زبان میں تنکیر کے لئے بھی آتی ہے اور تعظیم کے لئے بھی آتی ہے یعنی اس کے یہ معنے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی شخص یا چیز ایسی غیر معروف ہے کہ اس کا نام ہمیں معلوم نہیں یا ایسی بے حقیقت ہے کہ اس کا نام لینے کی ہمیں ضرورت نہیں اور یا پھر اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص یا وہ چیز جس پر تنوین آئی ہے نہایت ہی اہم اور عظیم الشان ہے اور جس بارہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایسا اہم امر ہے کہ ہر شخص کا ذہن اُدھر جا سکتا ہے اس لئے معرفہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی.اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًاکے تین معنے اوپر کی تشریحات کے مطابق اس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ اے یہودی قوم.یاد کرو جبکہ تم نے بحیثیت جماعت (۱) ایک عظیم الشّان انسان کو قتل کیا تھا یا قتل کرنا چاہا تھا(۲) یا کسی شخص کی پُشت پناہ بن کر یا اُسے انگیخت کر کے اور اُکسا کر کسی عظیم الشّان شخص کو قتل کرنا چاہا تھا یا قتل کیا تھا(۳) یا یہ کہ اے بنی اسرائیل جبکہ تم نے ایک غیر معروف شخص کو جس کا نام لینے کی ضرورت نہیں قتل کیا تھا یا قتل کرنا چاہا تھا اور پھر اس بارہ میں تم نے اختلاف کیا یعنی یا تو یہ کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا یا یہ کہا تھا کہ ہم نے قتل نہیں کروایا.یا یہ کہا تھا کہ ہم نے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی اور یا یہ کہا تھا کہ ہم نے قتل کروانے کی کوشش نہیں کی اور یا یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ایسا شخص قتل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا.ان معنوں میں سے یہ معنے کہ ایک غیر معروف شخص کو تم نے قتل کرنا چاہا تھا یا قتل کیا تھا سب سے کمزور معنے ہیں کیونکہ ایک غیر معروف شخص کے قتل کا نہ تو یہودی قوم ارادہ کر سکتی تھی کیونکہ اس میں قوم کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اور نہ ایسے شخص کے قتل کے متعلق قوم میں کوئی اختلاف پیدا ہونے کا امکان تھا پس جہاں تک نفسِ مضمون کا تعلق ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نَفْسًا سے اس جگہ ایسا شخص ہی مراد ہے جس کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن اس کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا ہے گویا وہ ایسا شخص ہے کہ بغیر نام لینے کے بھی اس کی طرف ذہن منتقل ہو سکتا ہے.وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ اور اﷲ تعالیٰ اسے نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے تھے یعنی کسی نہ کسی ذریعہ سے اﷲ تعالیٰ قاتل کا یا قتل کرنے کی انگیخت کرنے والے کا یا قتل کرنے یا کروانے کی کوشش کرنے والے کا بھانڈا پھوڑ دے گا اور اس کے چہرے پر سے نقاب اُٹھا دے گا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس عظیم الشّان انسان کو قتل کرنے
Page 189
والا یا قتل کروانے والا یا قتل کرنے یا کروانے کی کوشش کرنے والا کون شخص ہے.اسی طرح اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اﷲ تعالیٰ اس بُغض اور کینہ کو ظاہر کر دے گا جو اس قتل یا ارادۂ قتل کا موجب ہوا.چونکہ اس آیت کے مضمون کی تکمیل اگلی آیت میں ہوتی ہے اِس لئے اس آیت کی پوری تشریح اگلی آیت کے ماتحت کی جائے گی.فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا١ؕ كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ١ۙ وَ اس پر ہم نے کہا کہ اس کو (یعنی قاتل) کو اس (ضائع شدہ جان) کے (جرم قتل کے) ایک حصہ کے سبب سے يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۰۰۷۴ مارو.اللہ اسی طرح مُردوں کو زندہ کرتا اور تم کو اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو.حَلّ لُغَات.اِضْرِبُوْہُ.امر جمع مخاطب کا صیغہ ہے اور ضَرَبَہٗ بِیَدِہٖ وَ بِالْعَصَا کے معنے ہیں اَصَا بَہٗ وَ صَدَ مَہٗ بِھَا یعنی اس کو ہاتھ سے یا سونٹے سے یا کسی اور چیز سے مارا.نیز کہتے ہیں ضَرَبَ الشَّیْءَ بِالشَّیْ ءِ اور معنے یہ ہوتے ہیں خَلَطَہٗ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مِلا دیا.نیز کہتے ہیں ضَرَبَ لَہٗ مَثَـلًا اور مراد یہ ہوتی ہے وَصَفَہٗ وَ قَالَہٗ وَ بَیَّنَہٗ کسی مثال کو بیان کیا.(اقرب) ضَرَبَہٗ بِالسَّیْفِ: اَوْقَعَہٗ بِہٖ یعنی اس پر تلوار سے حملہ کیا.(اقرب )پس اِضْرِبُوْہٗ کے ایک معنی ہوں گے اس کو مارو.بِبَعْضِہَا.بَعْضُ کُلِّ شَیْ ءٍ کے معنے ہیں طَائِفَۃٌ مِّنْہُ ساری چیز کا ایک معتدبہ حصّہ وَقِیْلَ جُزْءٌ مِّنْہُ اور بعض محققین کے نزدیک کسی چیز کے ایک تھوڑے سے حصّہ پر بھی بعض کا لفظ بولا جاتا ہے وَیَجُوْزُ کَوْنُہٗ اَعْظَمَ مِنْ بَقِیَّتِہٖ کَالثَّمَانِیَۃِ مِنَ الْعَشَرَۃِ اور بعض کا لفظ کسی چیز کے بڑے حصّہ کے لئے بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسے دس میں سے آٹھ کو بعض کہیں گے حالانکہ آٹھ بقیہ دو ۲ سے بہت زیادہ ہیں.(اقرب) یُحْيٖ.اَحْيٰ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یُحْيٖ کے معنے ہیں وہ حیات بخشتا ہے یا وہ حیات بخشے گا.حیات کے معنی لغت میں (۱) نمو کے ظاہر ہونے کے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الروم :۲۰) یعنی اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے خشک اور ویران ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی اس میں سبزہ ،چارہ اُگاتا ہے (۲) دوسرے معنی حیات کے حِس کا درست ہونا ہے اور موت کے معنے حِس کے زائل
Page 190
ہونے کے ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا (مریم :۲۴) حضرت مریم ؑ نے دردِزِہ کے وقت میں فرمایا کاش میں اس سے پہلے بیہوش ہو جاتی.اس جگہ موت سے مراد حقیقی موت نہیں بلکہ درد کی وجہ سے انہوں نے بیہوشی کی خواہش کی ہے (۳) تیسرے معنی حیات کے علم اور عرفان کے ہوتے ہیں.اور موت کے معنی جہالت کے ہوتے ہیں.قرآن کریم میں آتا ہے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ (الانعام :۱۲۳) یعنی کیا وہ شخص جو جاہل ہو اور پھر ہم نے اسے علم رُوحانی بخشا ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس کے برخلاف ہے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى (الروم :۵۳) تو مُردوں کو نہیں سُنا سکتا.مراد یہ ہے کہ تو جاہلوں سے بات نہیں منوا سکتا (۴) زندگی سے مراد خوشیاں ہوتی ہیں اور موت کے معنے تکلیفوں اور دُکھوں کے ہوتے ہیں قرآن کریم میں ہے.يَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ(ابراہیم :۱۸)یعنی دوزخی کو چاروں طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرا ہوا نہ ہو گا.یعنی غم اور پریشانی لاحق ہو گی.مگر موت نہ آئے گی (۵) پانچویں معنی حیات کے جاگنے اور ہوشیار ہونے کے ہیں.اور اس کے بالمقابل موت کے معنی نیند کے ہیں (۶) چھٹے معنے حیات کے جاندار کا سانس لینا.یا سانس کی حالت کا پایا جانا ہے اور موت کے معنے اس کے سانس کا بند ہو جانا یا سانس کے بغیر ہونا ہے.اَلْمَوْتٰی.اَلْمَیِّتُ کی جمع ہے اور اَلْمَیِّتُ کے معنے ہیں اَلَّذِیْ فَارَقَ الْحَیٰوۃَ جس کے اندر حیات نہ رہے (اقرب) (موت.حیات کے مقابل کا لفظ ہے) جو معنی حیات کے ہوں اُس کے اُلٹ معنی موت کے ہوتے ہیں.زَوَالُ الْحَیَاۃِ عَنْ مَّنْ اِتَّصَفَ بِھَا : اس چیز سے زندگی کا علیحدہ ہو جانا جو زندگی کے ساتھ متصف ہو.(اقرب) مفردات میں ہے.اَلْمَوْتُ زَوَالُ الْقُوَّۃِ الْحَیَوَانِیَّۃِ وَاِبَانَۃُ الرُّوْحِ عَنِ الْجِسْمِ.قوت حیوانیہ اور رُوح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا موت کہلاتا ہے.اَنْوَاعُ الْمَوْتِ بِحَسْبِ الْحَیٰوۃِ.موت کئی قسم کی ہوتی ہے جس قسم کی زندگی ہو گی اسی کے مطابق موت ہو گی.(۱) فَالْاَوَّلُ مَاھُوَ بِـاِ زَاءِ الْقُوَّۃِ النَّامِیَّۃِ الْمَوْجُوْدَۃِ فِی الْاِنْسَانِ وَالْحَیَوَانَاتِ وَالنَّبَاتِ.انسان.حیوانات اور نباتات میں نشوونما کا رُک جانا موت کہلاتا ہے جیسے يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (الروم :۲۰) میں اشارہ فرمایا ہے (۲) اَلثَّانِیْ.زَوَالُ الْقُوَّۃِ الْحَاسَّۃِ احساس کا زوال بھی موت کہلاتا ہے جیسے حضرت مریم علیہ ا لسلام کا قوليٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا (مریم :۴ ۲) ہے کہ اے کاش میں اس سے پہلے کی بے حس ہو چکی ہوتی (۳) زَوَالُ الْقُوَّۃِ الْعَاقِلَۃِ زوال عقل یعنی جہالت بھی موت کہلاتی ہے جیسے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ (الانعام :۱۲۳) (۴) اَلرَّابِعُ.الْحُزْنُ الْمُکَدِّرَۃُ لِلْحَیٰوۃِ.ایسے غم جو زندگی کو دوبھر کر دیں جیسے فرمایا.يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ(ابراہیم :۱۸) (۵) اَلْخَامِس.اَلْمَنَامُ نیند.لسان میں ہے.وَقَدْ
Page 191
یُسْتَعَارُ الْمَوْتُ لِلْاَحْوَالِ الشَّاقَّۃِ کَالْفَقْرِ وَالذُّ لِ وَالسُّؤَالِ وَالْھَرَمِ وَالْمَعْصِیَۃِ.کبھی موت کا لفظ استعارۃً تکلیف دِہ حالتوں پر بھی جیسے فقر.ذ لّت.سوال.بڑھاپا اور معصیت ہیں بولا جاتا ہے.اٰیٰتِہٖ.اٰیٰتٌ.اٰیَۃٌ کی جمع ہے اور اٰیَۃٌ کے معنے علامت.نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں نیز قرآن کریم کے ہر ایسے ٹکڑے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جُدا کر دیا گیا ہو اٰیَۃٌ کہتے ہیں.(تاج ) تَعْقِلُوْنَ.عَقَلَ (یَعْقِلُ) سے مضارع مخاطب جمع کا صیغہ ہے اور عَقَلَ الدَّوَاءُ الْبَطْنَ کے معنے ہیں اَمْسَکَہٗ دوائی نے اس کے پیٹ کو روک دیا.یعنی قبض کر دی.اور جب عَقَلَ الْغُلَامُ کہیں تو معنے ہوں گے اَدْرَکَ لڑکا بالغ ہو گیا.یعنی اچھی اور بُری باتوں کو سمجھنے لگ گیا.اور عَقَلَ الشَّیْ ءَ عَقْلًا کے معنے ہیں فَھِمَہٗ وَ تَدَبَّرَہٗکسی چیز کو سمجھا اور اس کے متعلق غور و فکر کیا.عَقَلَ الْبَعِیْرَ.ثَنٰی وَظِیْفَہٗ مَعَ ذَرَاعِہٖ فَشَدَّھُمَا مَعًا بِحَبْلٍ اُونٹ کی ٹانگ کو اس کی ران کے ساتھ باندھ دیا.عَقَلَ الْوَعْلُ عَقْـلًا کے معنے ہیں صَعَدَ وَامْتَنَعَ فِی الْجَبَلِ الْعَالِیْپہاڑی بکر اپہاڑ پر چڑھ گیا اور وہاں جا کر رُک کر محفوظ ہو گیا.نیز اَلْعَقْلُ کے معنے ہیں نُوْرٌ رُوْحَانِیٌّ بِہٖ تُدْرِکُ النَّفْسُ الْعُلُوْمَ الضَّرُوْرِیَّۃَ وَالنَّظَرِیَّۃَ کہ عقل اس روحانی روشنی کا نام ہے جس کے ذریعہ سے نفس بدیہی باتوں کو یا غورو فکر سے معلوم ہونے والی باتوں کو معلوم کرتا ہے (اقرب) پس اَفَـلَا تَعْقِلُوْنَ کے معنے ہوں گے (۱) کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے (۲) کیا تم اپنی ناواجب حرکات سے رُکتے نہیں.تفسیر.اِضْرِبُوْہُ بِبَعْضِھَا میں باء کے معنے سببیت یا اِلْصَاق کے پس ہم نے اُن سے کہا کہ اس کو یعنی قاتل کو اُس کے یعنی مقتول کے بعض کے ساتھ یا بعض کے سبب سے مارو.ب کے معنے عربی زبان میں کئی ہوتے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں.اوّل.اِلْصَاق یعنی اس کے ساتھ ملا دینا جیسے کہا جاتا ہے اَمْسَکْتُ بِخَالِدٍ مَیں نے خالد کو پکڑ لیا یعنی میرا جسم اور اُس کا جسم مِل گیا.کبھی اِن معنوں میں یہ لفظ مجازاً بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں مَرَرْتُ بِزَیْدٍ میں زید کے پاس سے گزرا یعنی گو جسم جسم سے چھؤا نہیں مگر ایک رنگ میں قُرب حاصل ہو گیا.دوسرے معنے اس کے فعل لازم کو متعدّی بنانے کے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں ذَھَبْتُ بِزَیْدٍ مَیں زید کو لے گیا اور کبھی اس کے معنے امداد طلب کرنے کے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں نَجَوْتُ بِالْفَرَارِ بھاگ کر میں نے نجات حاصل کی یعنی بھاگنے سے مدد حاصل کی.کبھی اس کے معنے سببیّت کے ہوتے ہیں یعنی وہ چیز اس کا سبب بن گئی جیسے کہتے ہیں لَقِیْتُ بِزَیْدِنِ الْاَسَدَ زید کے سبب سے مَیں نے شیر کو دیکھا.یعنی زید اپنی قوت اور شوکت میں ایک شیر
Page 192
کی طرح ہے جس میں سے مَیں گویا شیر کا وجود دیکھنے کے قابل ہو گیا.اور کبھی اس کے معنے ساتھ ہونے کے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں اِھْبِطْ بِسَلَامٍ سلامتی کے ساتھ اُترو یعنی تم بھی اُترو اور تمہارے ساتھ سلامتی بھی اُترے.کبھی اس کے معنے تبعیض یعنی کچھ حِصّے کے ہوتے ہیں کہتے ہیں شَرِبَ بِمَاءِ الْبَحْرِ اس نے سمندر کے پانی کو پیا یعنی سمندر کے پانی کا کچھ حصّہ پیا.اسی طرح بکے معنے قَسم کے بھی ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں بِاللہِ کہ مَیں اﷲ کی قسم کھاتا ہوں اور کبھی یہ تاکید کے لئے بھی آتا ہے (اقرب) ان کے علاوہ عربی زبان میں اِس کے اَور بھی کئی معنے ہیں.اِس آیت میں صرف دو معنے چسپاں ہو سکتے ہیں ایک اِلصاق کے، دوسرے سببیّت یا تعلیل کے.اِلصاق کے لحاظ سے اِس آیت کے معنے یُوں ہوں گے کہ اس کے بعض کے ساتھ اسے مارو یعنی اس کا بعض حصّہ اس پر زور سے پھینکو.اور سببیّت یا تعلیل کے لحاظ سے اس کے معنے یہ ہوں گے کہ اس کے بعض (گناہ) کے سبب سے اسے مارو.كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى میں اِحیاءِ مَوتٰی سے مراد كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى کے دو معنی ہیں.اوّل یہ کہ اس طرح اﷲ تعالیٰ مُردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی حقیقی مُردوں کو زندہ کر کے اس دنیا میں واپس لاتا ہے.یہ معنے اس جگہ پر نہیں لئے جا سکتے کیونکہ قرآن شریف کی دوسری آیات ان معنوں کے خلاف ہیں اور اُن سے ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی مُردے اس دنیا سے واپس نہیں آسکتے.(دیکھئے تفسیر آیت نمبر ۵۷سورہ ھٰذا) دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ اﷲ تعالیٰ اس طرح ایسے لوگوں کو جو مُردوں کے مشابہ ہوتے ہیں زندہ کرتا ہے یا یہ کہ اﷲ تعالیٰ اس طرح مُردوں کی عزّت کو بچا لیتا ہے یا آئندہ دنیا کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے.آخری دونوں معنوں کی تصدیق قرآن کریم سے ہوتی ہے اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ(البقرۃ :۱۸۰) یعنی اے عقلمندو! قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے اگر مناسب موقع پر قاتل کو سزا دی جائے تو آئندہ قتل کے جُرم کم ہو جائیں گے اور اس طرح کئی لوگوں کی جانیں بچ جائیںگی.اس محاورہ کے رُو سے مُردے کو زندہ کرنے کے یہ معنے نہیں کہ جو مر چکا ہو اُسے زندہ کرنا.بلکہ یہ معنے ہیں کہ جس کے قتل ہونے کا خطرہ تھا اُس کو اِس خطرہ سے بچا لینا.اور اس رنگ میں بھی قصاص حیات ہے کہ جو مارا جاتا ہے اس کی عزّت قائم ہو جاتی ہے اور رشتہ داروں کے دلوں سے بُغض اور کینہ نکل جاتا ہے.اگر قاتل کو سزا نہ ملے تو رشتہ داروں کے دلوں میں بُغض اور کینہ باقی رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آدمی کو قتل کر کے اُس کی ذلّت کی گئی ہے.عربوں کی بول چال میں بھی یہ محاورہ پایا جاتا ہے چنانچہ ایک شاعر حارث بن حلزہ کہتا ہے ؎
Page 193
اِنْ نَبَشْتُمْ مَا بَیْنَ مَلْحَۃَ فَالصَّا قِبِ فِیْہِ الْأَمْوَاتُ وَ الْأَحْیَاءُ (سبعہ معلّقہ قصیدہ نمبر۷) یعنی اے ہماری دشمن قوم اگر تم ملحہ اور صاقب دونوں مقاموں کے درمیان قبروں کو کھود کر دیکھو تو ان قبروں میں تم کو مُردے بھی ملیں گے اور زندہ بھی ملیں گے.مطلب اس کا یہ ہے کہ ہماری قوم بہادر اور غیوّر ہے.جب کبھی ہمارے کسی آدمی کو تمہاری قوم کے کِسی آدمی نے مارا ہے تو ہم نے اُس کا بدلہ ضرور لے لیا ہے اور اس طرح ہمارا مُردہ زندہ ہو گیا لیکن جب ہمارے کسی آدمی نے تمہاری قوم کے کِسی آدمی کو مارا ہے تو تم اس کا بدلہ نہیں لے سکے پس تمہارے مُردے قبروں میں ذلیل رہے کیونکہ اُن کا بدلہ کسی نے نہیں لیا.یہ شعر عرب کے زمانۂ جاہلیت کے ایک چوٹی کے شاعر کا ہے اور اِس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عربی زبان میں مُردہ زندہ کرنے کے معنے یہ بھی ہیں کہ کسی مقتول کا بدلہ لے لیا جائے پس اس مفہوم کی رو سے كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى کے معنے یہ ہوں گے کہ اس طرح اﷲ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو اُس کی راہ میں قتل ہوئے ہوں یا اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہوں اُن کا بدلہ لے کر زندہ کر دیتا ہے.جیسا کہ مَیں اوپر بتا چکا ہوں ایک معنے اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مُردوں کی طرح ہوں اُن کو زندہ کر دینا.یہ معنے عام محاورہ کے مطابق ہیں بعض دفعہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ایسی مشابہ ہو جاتی ہے کہ اُس کا نام اسے مل جاتا ہے چنانچہ عام بول چال میں جب کسی شخص کو کوئی سخت چوٹ لگے تو وہ اپنے درد اور کرب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے ’’ ہائے میں مر گیا ‘‘مطلب یہ ہوتا ہےکہ مَیں مُردوں کی طرح ہو گیا.پس آیت کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مُردوں کی طرح ہوں اﷲ تعالیٰ اُن کو زندہ کر دیتا ہے یعنی جن کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی.اور دنیوی علوم ان کی ہلاکت کا فتویٰ دے دیتے ہیں خدا تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے بچا لیتا ہے.وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.اور تم کو اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تم غلطیوں اور گناہوں سے رُکو.عقل کے معنے حَلِّ لُغَات آیت نمبر ۴۵ سورۃ ھٰذا میں بتائے جا چکے ہیں کہ باندھنے اور روکنے اور رُکنے کے ہوتے ہیں.عقل کی قوت کو عقل اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں اور غلطیوں سے روک لیتا ہے.آیت کے اس ٹکڑہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر جس امر کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نشان ہے جس سے سمجھدار لوگ فائدہ اُٹھا کر گناہ اور بدی سے بچ سکتے ہیں یا کفر اور طغیان سے نجات پا سکتے ہیں.
Page 194
وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا....الخ میں بیان شدہ واقعہ کے متعلق پہلے مفسرین کا خیال ان دونوں آیتوں میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا اس کے متعلق پرانے مفسّرین کا خیال یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک مقتول سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اس کی تفصیل یُوں بیان کرتے ہیں کہ عامیل نامی ایک شخص کو (بقول کرمانی) یا نکار کو ( بقول ماوردی)اس کے بھتیجے نے اور بعض کے نزدیک اس کے بھائی نے قتل کر دیا تھا.اس پر اﷲ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کریں جس کا ذکر ان لوگوں کے نزدیک اوپر کی آیات میں آچکا ہے اور پھر حکم فرمایا کہ اس گائے کے بعض ٹکڑوں کو اس مقتول کے ساتھ مارو.وہ ٹکڑا جس کے مارنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بارہ میں مفسرین کا اختلاف ہے.بعضوں نے کہا ہے کہ اُس کی زبان کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا.بعضوں نے کہا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے آخری سرے کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا.بعضوں نے کہا ہے کہ اُس کی دائیں ران کے مارنے کا حکم دیا گیا تھا.حضرت ابن عباسؓ کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ جس ہڈی سے کان نکلے ہیں.اُس ہڈی کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا.جب انہوں نے ایسا کیا تو اﷲتعالیٰ نے اس گائے کے ٹکڑے کے مارنے سے مُردے کو زندہ کر دیا.(فتح البیان زیر آیت ھٰذا) اختلاف کے بارہ میں کہتے ہیں کہ قاتل نے لاش ایک ایسی جگہ پھینک دی تھی جو کئی قبائل کے درمیان واقع تھی اس وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا.ہر قبیلہ نے کہا کہ دوسروں نے مارا ہے ہم نے نہیں مارا.مفسرین اس بات کی وجہ تلاش کرنے میں بھی لگ گئے ہیں کہ قاتل نے کیوں مارا.بعض کہتے ہیں کہ مقتول کی لڑکی خوبصورت تھی اُس سے شادی کرنے کے لئے اُس نے چچا کو مارا.بعض کہتے ہیں کہ قاتل غریب تھا.وہ چاہتا تھا کہ اپنے چچا یا بھائی کو مار کر اس کا وارث بن جائے.علاّمہ قرطبی نے تو اس واقعہ سے بعض مسائل اسلامیہ کا استخراج بھی کیا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ تفسیریں جو کی گئی ہیں ان کا کوئی حصّہ بھی قرآن کریم یا حدیث سے ثابت نہیں.وَاِذْ قَتَلْتُمْ میں بیان شدہ واقعہ کے متعلق سابق مفسرین کے خیالات کے متعلق ابن کثیر کی رائے اسی وجہ سے علاّمہ ابنِ کثیر نے ان روایات کو درج کر کے آخر میں لکھا ہے وَظَاھِرٌ اَنَّھَا مَاْخُوْذَۃٌ مِنْ کُتُبِ بَنِٓیْ اِسْرَائِیْلَ وَھِیَ مِمَّا یَجُوْزُ نَقْلُہَا وَلٰـکِنْ لَّا نُصَدَّقُ وَلَا نُکَذَّبُ فَلِھٰذَا لَا یُعْتَمَدُ عَلَیْھَا اِلَّا مَا وَافَقَ الْحَقَّ عِنْدَ نَا ( ابن کثیر زیر آیت اِنَّ اللہُ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تَذبَحُوْا بَقَرَۃً ) یعنی یہ ظاہر بات ہے کہ یہ سب قصّے بنی اسرائیل کی کتابوں سے لئے گئے ہیں اور ان قصّوں کا نقل کرنا تو جائز ہے لیکن ان کی تصدیق یا تکذیب کرنا جائز نہیں پس ایسے قصّوں پر کسی صورت میں بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہاں صرف اِس صورت میں ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ اس
Page 195
تعلیم کے مطابق ہوں جو قرآن یا حدیث سے ثابت ہے.تفسیر فتح البیان میں بھی گائے کے ٹکڑوں کا ذکر کرتے ہوئے باوجود اِس کے کہ اُن میں سے ایک روایت حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب کی گئی ہے لکھا ہے وَ لَا حَاجَۃَ اِلٰی ذٰلِکَ مَعَ مَا فِیْہِ مِنَ الْقَوْلِ بِغَیْرِعِلْمٍ وَ یَکْفِیْنَا اَنْ نَّقُوْلَ اَمَرَھُمُ اللہُ تَعَالٰی اَنْ یَّضْرِبُوْہُ بِبَعْضِھَا یعنی ہمیں اس قسم کی روایتوں کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں خصوصًا جبکہ اُن میں ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن کی تصدیق علم سے نہیں ہو سکتی.ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اﷲ تعالیٰ نے اُن کو اُس کے بعض سے مارنے کا حکم دیا تھا.صاحبِ فتح البیان کا یہ بیان بھی اس امر پر شاہد ہے کہ اس بارہ میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں باوجود اس کے کہ ان کو صحابہؓ تک پہنچایا گیا ہے وہ اسلامی روایات کہلانے کی مستحق نہیں بلکہ صرف یہودی کتابوں کی نقل ہیں پس ان پر اعتماد کرنا اسلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا ہے جو بالکل ممکن ہے کہ اسلام کی تعلیم کے صریح مخالف ہوں اور قرآن کریم کی تکذیب کرنے والی ہوں.قرآن مجید کی آیات کی ترتیب سابق مفسرّین کے خیالات کی تردید میں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اُس کی ترتیب ان روایات کی برداشت ہی نہیں کر سکتے.اوّل تو جو واقعہ تفسیروں میں بیان کیا گیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک قتل کے واقعہ پر قاتل کو دریافت کرنے کے لئے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا.لیکن قرآن کریم میں گائے کے ذبح کرنے کا حکم پہلے آتا ہے اور قتل کا واقعہ بعد میں آتا ہے.قرآن کریم تو اﷲ تعالیٰ کی کتاب ہے.اور فصاحت و بلاغت کے تمام انسانی معیاروں سے بالا ہے.ایک ادنیٰ عقل کا انسان بھی اس واقعہ کو اس ترتیب سے بیان نہیں کر سکتا.ہم میں سے ہر شخص اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اگر اس واقعہ کو بیان کرے تو وہ اِس طرح بیان کرے گا کہ یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس کے قتل کے بارہ میں اختلاف کیا تب ہم نے حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے کچھ حصّے کو مقتول کے کچھ حصّے پر مارو.جب تم نے ایسا کیا تو مردہ زندہ ہو گیا.لیکن قرآن کریم یوں بیان نہیں کرتا.قرآن کریم گائے کے واقعہ کو الگ بیان کرتا ہے اور قتل کے واقعہ کو الگ بیان کرتا ہے اور گائے کے واقعہ کو قتل کے واقعہ سے پہلے بیان کرتا ہے.پھر یہ کیونکر کہا جا سکتا ہے کہ یہ گائے قاتل کو دریافت کرنے کے لئے ذبح کی گئی تھی.قرآن کریم کی اس فصاحت و بلاغت کا خیال نہ بھی رکھا جائے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے بلکہ ایک معمولی لیکن معقول کتاب اُسے قرار دیا جائے تب بھی یہ ترتیبِ بیان اس کی طرف منسوب کرنی جائز نہیں ہو سکتی.یہ اعتراض مَیں ہی نہیں کر رہا پہلے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ اعتراض
Page 196
پیدا ہوا ہے چنانچہ امام رازی نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں اس سوال کو اُٹھایا لیکن اس کا نہایت بودا جواب دیا ہے اور لکھا ہے کہ واقعہ کے تقدّم اور تأخرّ کو اسی ترتیب سے بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ کبھی سبب کو حکم سے پہلے بیان کر دیتے ہیں اور کبھی حکم کو سبب سے پہلے بیان کر دیتے ہیں اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ کبھی کبھی ترتیب میں فرق ہو جاتا ہے اور بیان کی ترتیب واقعہ کی ترتیب سے مختلف ہو جاتی ہے مگر ایسا اسی صورت میں ہوتا ہے جبکہ بعد میں ہونے والا واقعہ زیادہ اہم ہو.پس توجہ پھرانے کے لئے اسے پہلے بیان کر دیا جاتا ہے مثلاً کوئی شخص کسی مقتول کی لاش پر پہنچتا ہے تو جب وہ اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سناتا ہے تو پہلے یکدم سنا دیتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا اور پھر تفصیل بتاتا ہے کہ مَیں اس اس طرح جا رہا تھا کہ فلاں شخص کی لاش نظر آ گئی لیکن اس جگہ پر تو نہ صرف یہ کہ پہلی بات کو پیچھے بیان کیا گیا ہے اور پچھلی بات کو پہلے بیان کیا گیا ہے بلکہ اہمیت کے لحاظ سے جو بات ادنیٰ تھی اسے پہلے بیان کیا گیا ہے اور اہمیت کے لحاظ سے جو بات زیادہ تھی اسے بعد میں بیان کیا گیا ہے.اَور پچھلی بات کو پہلے بیان کرنے کی جو حکمت ہوا کرتی ہے وہ یہاں مفقود ہے.پس خالی یہ کہہ دینا کہ کبھی بعد کی بات کو پہلے بیان کر دیا کرتے ہیں کافی نہیں ہے.بلکہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ جن وجوہ کے پائے جانے پر بعد کی بات کو پہلے بیان کیا کرتے ہیں وہ اس جگہ پر پائی جاتی ہیں ورنہ قرآن کریم کا یہ حصہ حکمت سے خالی سمجھا جائے گا مگر میں بتا چکا ہوں کہ وہ وجوہ جو کسی بعد کی بات کو پہلے بیان کرنے کا سبب ہوا کرتی ہیں وہ یہاں نہیں پائی جاتیں بلکہ اسکے برخلاف یہ وجہ موجود ہے کہ جو پہلے کا واقعہ ہے اسے پہلے بیان کیا جاتا اور جو بعدکا واقعہ ہے اسے بعد میں بیان کیا جاتا کیونکہ پہلے کا واقعہ یعنی قتل بعد کے واقعہ یعنی گائے کے ذبح کرنے کے حکم سے زیادہ اہم ہے پس اصل ترتیب کو قائم رکھنے کی اشد ضرورت تھی.دوسرے یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ اﷲ تعالیٰ نے گائے کے واقعہ کو بھی اِذْ کے لفظ سے شروع کیا ہے اور قتل کے واقعہ کو بھی اِذ کے لفظ سے شروع کیا ہے اور ان آیات سے پہلے جتنی آیات گزری ہیں ان میں جہاں جہاں اِذْ کا لفظ آیا ہے وہ الگ واقعات کے متعلق آیا ہے پس اس جگہ بھی جبکہ دونوں آیتوں سے پہلے اِذْ کا لفظ آیا ہے ہمیں ماننا پڑے گاکہ یہ واقعات اپنی ذات میں الگ الگ ہیں.تیسری دلیل میرے خیال کی تائید میں یہ ہے کہ گائے کے ٹکڑے کو قاتل پر مار کر اُسے زندہ کرنے کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں اگر معجزانہ طور پر مُردے کو زندہ کرنا تھا تو اُس کے لئے گائے کے ذبح کرنے اور اُس کا ٹکڑا اس پر مارنے کی ضرورت کیا تھی.وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیا جاسکتا تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عام مسلمانوں کے نزدیک مُردے زندہ ہوتے رہے ہیں.لیکن اگر یہ کہا جائے کہ گائے کے گوشت میں کوئی طبّی
Page 197
اثر ایساہوتا ہے کہ مُردہ زندہ ہو جاتا ہے تو اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ وہ طبّی اثر اب کیوں ظاہر نہیں ہوتا اور اگر کہا جائے کہ صرف اس قسم کی گائے کے گوشت میں وہ طبّی اثر ہوتاہے جس کا ذکر اوپر کی آیات میں کیا گیا ہے تو اس پر یہ اعتراض پڑتا ہے کہ اگر اِن صفات والی گائے میں یہ اثر ہے تو پہلے اﷲتعالیٰ نے عام گائے کے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا.نیز اس قسم کی گائے کا مہیّا کرنا کوئی مشکل نہیں.اب بھی تلاش سے ایسی گائے مِل سکتی ہے.اس عقیدہ کے قائل اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں.غرض کوئی معقول وجہ اِن دونوں آیتوں کو آپس میں ملانے کی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ یہودیوں کی روایات کی بناء پر ان دونوں آیتوں کو ایک ہی واقعہ کی تفصیلات قرار دیا جائے مگر مشکل یہ ہے کہ یہود کی معتبر روایات بھی اس کے خلاف ہیں.وَاِذْ قَتَلْتُمْ کی تفسیر میں سابق مفسرین کے خیالات کی تردید بائبل سے بائبل میں کسی ایسے واقعہ کا ذکر نہیں جہاں گائے کو ذبح کر کے کسی مُردے پر مارا ہو اور وہ زندہ ہو گیا ہو.بیشک تورات استثناء باب ۲۱ آیت ۱ تا ۷ میں یوں آتا ہے.’’ اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے.تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گِردا گِرد کے شہروں کے فاصلہ کو ناپیں اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو.اس شہر کے بزرگ ایک بچھیا لیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو.اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو.اور اس شہر کے بزرگ اس بچھیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں اور وہاں اس وادی میں اس بچھیا کی گردن توڑیں.تب بنی لاوی جو کاہن ہیں نزدیک آئیں کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اُس کے نام سے برکت دیا کریں اور انہیں کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہوا کرے.پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچھیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی.اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور یُوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا.اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے.‘‘ ا س حوالہ سے ظاہر ہے کہ یہ گائے کے ذبح کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ اس کے کسی حصّہ کو مقتول پر مارا جائے نہ اس کا کوئی ذکر ہے کہ ایسا کیا گیا اور اس سے مُردہ زندہ ہو گیا اور اُس نے قاتل کی نشان دہی کی.بلکہ گائے کے ذبح کرنے میں صرف یہ حکمت ہے کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کے دلوں سے گائے کا شرک دُور ہو دوسرے چونکہ وہ اسے مقدّس سمجھتے تھے اس پر ہاتھ دھو کر گواہی دینے کا مطالبہ کرکے ان سے سچ بلوانے کی کوشش کی گئی ہے.
Page 198
جب واقعات یہ ہیں تو پھر وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب جن معنوں کو ردّ کرتی ہے.بائبل میں جن معنوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اُن کو زبردستی قرآن کریم کی آیات پرٹھو نسا جائے اور ایسے معنے کئے جائیں جو عقل اور نقل کے خلاف ہیں اور دشمن کو قرآن کریم پر ہنسی کرنے کا موقع دیتے ہیں حالانکہ قرآن کریم کا مضمون واضح ہے.اس زمانہ کے بنی اسرائیل میں بچھڑے کی پوجا اور گائے کی پوجا کے امکانات صریح طور پر پائے جاتے تھے.گائے کی قربانی کا حکم بھی بائبل میں موجود ہے اور اس میں جو اُس کی غرض بتائی گئی ہے وہ بھی قرآن کریم کے مفہوم کے مطابق معلوم ہوتی ہے یعنی یہودیوں کے دلوں سے گائے کے شرک کو دُور کرنا.ان سب امور کی موجودگی کے باوجود اس آیت کے مضحکہ خیز معنے کرنا اور قرآن شریف کی آیات کی لطیف ترتیب کو بگاڑ کر ایک غیر معقول ترتیب اس کی طرف منسوب کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے اور جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ قصص جن کی بناء پر ان آیات کے وہ معنے مفسرین نے کئے ہیں درست نہیں.بائبل سے وہ ثابت نہیں.قرآن کریم اُن کی تصدیق نہیں کرتا.رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے اُن کے متعلق کچھ بیان نہیں فرمایا تو اب ہمارے لئے یہ رستہ بالکل کُھلا ہے اور یہی رستہ طبعی ہے کہ ہم گائے کے ذبح کرنے کے واقعہ کو بالکل الگ سمجھیں اور قتل کے واقعہ کو بالکل الگ سمجھیں اور اِذْ قَتَلْتُمْ کےالفاظ والی آیت کو اُن یہودی قصّوں، کہانیوں سے جن کی تردید خود بائبل سے بھی ہوتی ہے آزاد رکھ کر معنی کریں.سابق مفسرین کے خیالات کے مطابق وَاِذْ قَتَلْتُمْکے امکانی معنے ہاں اگر مفسّرین کے خیالات کو تسلیم کر کے بطور تنزّل اس آیت کے معنے کرنے ہی پڑیں تو پھر بھی یاد رہے کہ اس آیت کے معنے یہ نہیں کئے جا سکتے کہ کوئی مُردہ گائے کے گوشت کے مارنے سے زندہ ہو گیا کیونکہ یہ معنی قرآن کریم کے صریح خلاف ہیں بلکہ صرف یہی معنی کئے جا سکیں گے کہ گائے کا ٹکڑہ مارنے سے کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جس سے قاتل پکڑا گیا اور خدا تعالیٰ نے یہ ترکیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لئے بتلائی تاکہ قاتل پکڑا جائے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی ٔ سلسلہ احمدیہ نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں یہ تشریح کی ہے لیکن جیسا کہ موقع اور محل سے ثابت ہے یہ تشریح مخالف کو قریب ترین رستہ سے پکڑنے کے لئے ہے.اس جگہ پر آپ نے اس آیت کی خود تفسیر بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کے اس استدلال کو ردّ کیا ہے کہ وہ اس آیت سے مُر دہ زندہ ہونے کا استدلال کرتا ہے.آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حقیقی مرُدہ کے زندہ ہونے کا ذکر نہیں صرف یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ گائے کا ٹکڑا مارنے سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی جس سے قاتل پکڑا گیا.غرض چونکہ اعتراض کے جواب میں آپ نے یہ معنے بیان فرمائے ہیں اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ مخالف کی باتوں کو مان بھی لیا جائے تو اس سے وہ استدلال نہیں ہو سکتا جو وہ کرتا ہے.ہمارے ملک میں لوگ چور کے
Page 199
پکڑنے کے لئے کسی چیز پر سیاہی لگا دیتے ہیں اور ان جاہل لوگوں کو جن پر چوری کا شبہ ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤکمرہ میں جا کر اُس چیز کو ہاتھ لگاؤ جو چور ہو گا اُس کا ہاتھ اس چیز سے چپک جائے گا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چور نہیں ہوتے وہ تو ہاتھ لگا آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو سیاہی لگ جاتی ہے مگر چور پکڑے جانے کے ڈر سے ہاتھ نہیں لگاتا اور اس کے ہاتھ کو سیاہی نہیں لگتی اور اس طرح پکڑا جاتا ہے.ہم ان قصص کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سہل راستہ مخالف کو خاموش کرانے کا اختیار کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ہی ترکیب جس میں اس امر کو مدّنظر رکھ لیا گیا ہو کہ سچائی کو نقصان نہ پہنچے اور دھوکا نہ ہو.اگر اﷲ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی ہو تو اس سے مُردہ زندہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا یا مثلاً ہم یہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ اﷲ تعالیٰ نے اس موقع پر نشان کے طور پر کوئی بات ایسی ظاہر کر دی جس سے گائے کے ٹکڑے مارنے والوں میں سے جو قاتل تھا اس کا پتہ لگ گیا.مثلاً یہی کہ اُس پرڈر کے مارے لرزہ طاری ہو گیا یا قاتل کے ٹکڑہ مارتے وقت مقتول کے جسم میں کسی اور سبب سے حرکت پیدا ہوئی اور قاتل یہ سمجھ کر کہ شائد وہ زندہ ہونے لگا ہے بیہوش ہو گیا یا ڈر کے مارے اُس نے اپنے جُرم کا اقرار کر لیا.بہر حال اس آیت سے کسی مُردے کا زندہ ہونا اور مجرم کا پکڑوانا ہرگز ثابت نہیں ہوتا.مگر یہ معنے بطور فرض کے اختیار کئے گئے ہیں اور مفسّرین کے معنوں کو ردّ نہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کو اِس اعتراض سے بچانے کے لئے ہیں کہ اس میں تضاد پایا جاتا ہے.کسی جگہ کہا ہے مُردے زندہ نہیں ہو سکتے اور کسی جگہ مُردے زندہ ہونے کی خبر دی ہے ورنہ میرے نزدیک اس آیت میں ایک مستقل مضمون بیان کیا گیا ہے اور اُن یہودی روایات سے جو خود ان کی اپنی کتابوں کے خلاف ہیں ہمیں استدلال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًاکی تشریح احمدی علماء کے نزدیک اور بعض اشکال پیشتر اس کے کہ مَیں وہ مفہوم بیان کروں جو میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے.مَیں ایک اور معنی بیان کرتا ہوں جو جماعتِ احمدیہ کے بعض علماء کرتے ہیں اور جن معنوں میں اسی اصل کو مدّنظر رکھا گیا ہے کہ اِذْقَتَلْتُمْ والے واقعہ کا ذبحِ بقرہ والے واقعہ سے کوئی واقعاتی جوڑ نہیں.اِن علماء کے نزدیک نَفْسًا سے مراد حضرت مسیح ناصری علیہ السلام ہیں اور قَتَلْتُمْسے مراد کوششِ قتل ہے یا مشابہ بالقتل کے معنے ہیں.ان کی تفسیر کے مطابق اس آیت کے معنے یہ ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے ایک عظیم الشّان جان یعنی حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا یا ان سے ایسا سلوک کیا کہ وہ مقتولوں کے مشابہ ہو گئے یعنی ان کو صلیب پر لٹکا کر مارنا چاہا.فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا.اِس میں ھَا کی ضمیر نفس کی طرف بھی جا سکتی ہے اور واقعۂ قتل کی طرف بھی معنوی طور پر
Page 200
جا سکتی ہے.اور مراد یہ ہے کہ اِس واقعۂ صلیب کے بعد تم نے اُس نفس کے متعلق اختلاف کیا یا یہ کہ اِس واقعہ کے متعلق اختلاف کیا.اگر واقعہ کے متعلق اختلاف لیا جائے تو اِس سے مراد یہ ہو گی کہ بعض نے یہ سمجھا کہ مسیحؑ صلیب پر مر گیا ہے اور بعض نے یہ سمجھا کہ مسیحؑ صلیب پر نہیں مرا.اور اگر نفس کی طرف ضمیر پھیری جائے تو اِس صورت میں اس کے یہ معنے بنیں گے کہ تم نے مسیحؑ کے بارہ میں اختلاف کیا یعنی بعض نے یہ سمجھا کہ مسیح کی لاش چرُالی گئی ہے حالانکہ وہ مر گیا تھا اور بعض نے یہ قرار دیا کہ مسیح علیہ السلام زندہ صلیب پر سے اُتار لئے گئے تھے اور قبر میں سے بھاگ گئے.وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ.میں اُن کے نزدیک اِس طرف اشارہ ہے کہ ایک دن اِن اختلافات کی حقیقت کو کھول دیا جائے گا.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بانی ٔ سلسلہ احمدیہ نے قرآنِ کریم ، انا جیل اور تاریخ سے یہ امرثابت کر دیا کہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام صلیب پر چڑھائے ضرور گئے تھے مگر مرے نہیں تھے اور وہ زندہ اُتار لئے گئے تھے چنانچہ تین دن قبر میں رہ کر وہ پھر اپنے حواریوں میں چلے آئے.فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا کے معنے وہ علماء یہ کرتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ مسیح کی قاتل قوم کو اِس جرم کے بدلہ میں جو اُس نے مسیح ؑ کے حق میں کیا ہے مارو یعنی سزا اور عذاب دو.گویا ہُ کی ضمیر قومِ یہود کی طرف جاتی ہے جو قاتل تھی اور ھَا کی ضمیر نفس کی طرف جاتی ہے جس سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام ہیں اور جُرم کے بعض حصّے سے مراد یہ ہے کہ کچھ حصّہ کی سزا فرشتے اُن کو دنیا میں دیں اور کچھ حصّہ کی سزا مرنے کے بعد انہیں ملے گی.حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب کے واقعہ کے متعلق سورۂ نساء رکوع ۲۲.آیت ایک سو اٹھاون میں بحث آئے گی اِس جگہ اوپر کے معنوں کو سمجھنے کے لئے اختصاراً اس قدر بتا دینا کافی ہے کہ حضرت مسیح ناصریؑ کے واقعۂ صلیب کے متعلق مختلف اقوام میں اختلاف پایا جاتا ہے.یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیحؑ کو انہوں نے صلیب پر لٹکا دیا اور صلیب پر ہی وہ مر گئے پھر اُن کی لاش کو ایک قبر میں رکھ دیا گیا جہاں سے اُن کے مرید اُن کی لاش کو اُٹھا کر لے گئے اور لوگوں میں یہ مشہور کر دیا کہ حضرت مسیح زندہ ہو گئے ہیں تاکہ وہ یہودیوں کے اس اعتراض سے بچ جائیں کہ جو شخص صلیب پر لٹکا کے مار دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے ( جس کی موت صلیب پر لٹک کر ہو اس کے متعلق لعنتی ہونے کا فتویٰ بائبل میں موجود ہے چنانچہ لکھا ہے.’’ وہ جو پھانسی دیا جاتا ہے خدا کا ملعون ہے‘‘ استثنا باب ۲۱ آیت ۲۳ ’’جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے ‘‘(گلتیوں باب ۳ آیت ۱۳) مسیحیوں کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب پر ضرور لٹکایا گیا تھا اور وہ صلیب پر مر بھی گئے لیکن چونکہ اُن کا صلیب پر لٹکایا جانا بغیر کسی گناہ کے تھا اس لئے مسیحیوں کے نزدیک گو حضرت مسیحؑ لعنتی ہوئے مگر وہ دوسروں کی خاطر لعنتی ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر انہوں نے
Page 201
اس لعنت سے نجات پا لی جو بنی نوع انسان کو گناہ کی سزا سے بچانے کے لئے انہوں نے اپنے آپ پر خوشی سے وارد کی تھی.آج کل کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح ؑ صلیب پر نہیں لٹکائے گئے بلکہ ان کی جگہ کسی اور شخص کو صلیب پر لٹکا دیا گیا اور اُن کو خدا تعالیٰ آسمان پر زندہ اُٹھا کر لے گیا.اس عقیدہ کا ثبوت کسی حدیث سے نہیں ملتا جو تفصیلات اس واقعہ کی بیان کی جاتی ہیں وہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جاتیں.گذشتہ زمانہ کی تفصیلات یا تو نبی کو الہام سے معلوم ہو سکتی ہیں یا صحیح تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہیں چونکہ وہ تفصیلات رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے بیان نہیں فرمائیں لازماً اُن کا ثبوت تاریخ سے دینا پڑے گا لیکن جیسا کہ میں بتا چکا ہوں نہ یہودی تاریخ میں اور نہ ہی عیسائی تاریخ میں اِن باتوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے.پس سوائے اس کے کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ بعض شریر یہودیوں یا عیسائیوں نے اپنی تاریخوں کے خلاف روائتیں وضع کر کے مسلمانوں کے ساتھ تمسخر کیا.بانی ٔ سلسِلہ احمدیہ نے ان تینوں اقوال سے اختلاف کیا ہے اور قرآن کریم، اناجیل اور تاریخ سے اس امر کو ثابت کیا ہے کہ حضرت مسیح صلیب پر تو لٹکائے گئے تھے مگر خود حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق جو انجیل میں بیان ہیں اور آج تک محفوظ ہیں صلیب پر سے زندہ اُتار لئے گئے اور زخموں کی شدّت سے دو تین دن بیہوشی اور ضعف کی حالت میں ایک کمرہ میں پڑے رہے.تیسرے دن طاقت آنے پر وہاں سے نکلے اور حواریوں کی مدد سے اور انجیل کی اس پیشگوئی کے مطابق کہ مسیحؑ بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو جمع کرنے کے لئے آیا ہے ( لکھا ہے کہ ’’ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں.مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے ‘‘ یوحنا باب ۱۰ آیت ۱۶) ان دس قبائل میں تبلیغ کرنے کے لئے روانہ ہو گئے جن کی نسبت بائبل اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بخت نصر اُنہیں قید کر کے عراقِ فارس کی طرف لے گیا اور وہاں سے اُس نے اُنہیں سلطنت کے مشرقی ممالک یعنی افغانستان اور کشمیر کی طرف پھیلا دیا تھا.ان علماء کا خیال ہے کہ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے کہ تمہاری شرارتیں صرف موسیٰ ؑ کے زمانہ پر ختم نہیں ہو گئیں بلکہ ان کا سلسلہ ممتد ہوتا گیا یہاں تک کہ تم نے مسیح ناصریؑ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی اور اسے لعنتی قرار دیا لیکن اﷲ تعالیٰ ایک دن تمہارے اس راز کو کھول کر رکھ دے گا.جہاں تک معانی کا سوال ہے یہ تفسیر بہت حد تک اس آیت پر چسپاں ہوتی ہے مگر میرے نزدیک اس میں
Page 202
بعض اشکال ہیں مثلاً یہ کہ اِس کے بعد کی آیت کو ثُمَّ کے لفظ سے شروع کیا گیا ہے اور ثُمَّ کے عام معنے یہ ہوتے ہیں کہ پہلے واقعہ کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہوا.اگر وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ اور اس کے بعد کی آیت کے معنے یہ کئے جائیں کہ مسیح ؑ موعود کے زمانہ میں اﷲ تعالیٰ اس راز کو ظاہر کر دے گا تو ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ والی آیت جو اس کے آگے ہے اس کے معنے یہ کرنے پڑیں گے کہ واقعۂ قتل کے بعد نہیں بلکہ اس اظہار کے بعد جو آخری زمانہ میں ہونے والا ہے یہودیوں کے دل سخت ہو گئے حالانکہ یہ درست نہیں.یہود کے دل جہاں تک مسیح علیہ السلام پر ظلم کرنے کا تعلق ہے حضرت مسیحؑ کو صلیب پر لٹکاتے ہوئے ہی سخت ہو گئے تھے.اِذْقَتَلْتُمْ نَفْسًا....الخ کے مرجح معنے اب مَیں ان معنوں کی طرف آتا ہوں جنہیں مَیں ترجیح دیتا ہوں لیکن ان معنوں کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ گزشتہ مفسّرین کو غلطی اس وجہ سے لگی ہے کہ انہوں نے اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا والے واقعہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ سمجھ لیا حالانکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا نہیں وَ مَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ تک وہ واقعات ختم ہو گئے ہیں جن میں بنی اسرائیل کی وہ نافرمانیاں اور ناشکریاں بیان کی گئی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان سے ہوئیں اور وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا کی آیت سے میرے نزدیک اُن کی اُن نافرمانیوں اور ناشکریوںکا ذکر کیا گیا ہے جو رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے زمانہ میں اُن سے صادر ہوئیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قتل والے واقعہ کے بعد فرماتا ہےثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ پھر اس واقعہ کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے یعنی تم نے اس سے عبرت حاصل نہ کی.اور اس آیت کے آخر میں فرماتا ہے وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ اور اﷲ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو جس سے معلوم ہوا کہ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ والے گروہ ہی نے ایک جان کو مارا یا مارنے کی کوشش کی تھی اور وہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے زمانہ کا تھا.تبھی تو فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اﷲ اس سے غافل نہیں.اسی طرح اِس آیت کے بعد بھی اَفَتَطْمَعُوْنَ۠ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ والی آیت میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے زمانہ کے لوگ تھے.پس حقیقت یہ ہے کہ آٹھویں رکوع تک تو یہودیوں کی ان ناشکریوں کا ذکر ہے جوحضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اُن سے صادر ہوئیں اور نویں رکوع سے ان کی اُن ناشکریوں کا ذکر شروع ہوتاہے جو رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے زمانہ میں اُن سے سرزد ہوئیں.اِذْقَتَلْتُمْ نَفْسًا میں مخالفین اسلام کے کعب بن اشرف کے قتل کے متعلق اعتراض کا جواب رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے زمانہ کا ایک واقعہ ہمیشہ مخالفینِ اسلام کے لئے اعتراض کا موجب بنتا چلا آیا
Page 203
ہے اور وہ واقعہ کعب بن اشرف اور ابورافع سلام بن ابی الحقیق دو یہودی سرداروں کے قتل کا ہے.ان دونوں کو رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے حکم کے ساتھ قتل کیا گیا تھا.مخالفین اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ لڑائی میں قتل یا لڑائی کے نتیجہ میں قتل تو خیر جائز کہلا سکتا ہے مگر ان دوشخصوں نے تو نہ لڑائی کی تھی نہ یہ کسی لڑائی کے جُرم میں پکڑے گئے تھے پھر انہیں کیوں قتل کیا گیا.میرے نزدیک اس آیت میں اسی واقعہ کی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ قتل قومی جرائم کے نتیجہ میں تھے اور یہودی قوم ان کی ذمہ وار تھی.رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہ وسلم پر کوئی اعتراض نہیں آتا کیونکہ انہوںنے جو کچھ کیا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اور جائز قصاص کی صورت میں کیا.تشریح اس اجمال کی یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب اﷲ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح دی تو یہود جنہوں نے رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے مدینہ میں ورود کے موقع پر مسلمانوں سے سمجھوتہ کر لیا تھا ان کے دل حسد سے جل گئے اور منافقین کے دلوں میں بھی اُس وقت سے بُغض کی آ گ سلگنے لگی.درحقیقت بدر کی جنگ نے ایک طرف تو کفّار مکّہ کی شوکت کو توڑ دیا اور دوسری طرف یہود اور منافقین کے دلوں میں بھی بے چینی پیدا کر دی کیونکہ اس سے پہلے وہ مسلمانوں کی آمد کو ایک وقتی اور معمولی تغیر سمجھتے تھے مگر اس جنگ کے بعد وہ اسکی اہمیت کو محسوس کرنے لگ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو منافقوں نے اندرونی طور پر ریشہ دوانیاں شروع کر دیں.دوسری طرف یہودی سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں کے خلاف یہودی قوم کو مختلف ذرائع سے بھڑکانا شروع کر دیا.اور مکّہ والوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جوش دلانا شروع کر دیا اور ابورافع ابن حقیق نے اس کی پیٹھ ٹھونکی چنانچہ جنگ بدر ۲ ہجری کے رمضان کی سترھویں یا انیسویں تاریخ کو ہوئی اور اس جنگ کے معًا بعد کعب بن اشرف مکّہ گیا اور اس نے مکّہ والوں میں مسلمانوں سے بدر کے واقعہ کا بدلہ لینے کے لئے اشتعال پیدا کیا اور بڑے جوش سے کفار مقتولین کے مرثیے پڑھے اور قریش کو غیرت دلائی اور یہاں تک شرارت میں بڑھ گیا کہ مسلمان عورتوں کی نسبت تشبیب شروع کر دی یعنی ایسے شعر کہنے شروع کر دیئے جن میں مسلمان مستورات کی نسبت محبت کا اظہار ہوتا تھا.یہ شعر لوگ پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف اُن کے دلوں میں جوش بھی پیدا ہوتا تھا اور ان کا رُعب بھی مٹتاتھا.بڑھتے بڑھتے اِس ناپاک انسان نے رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہ ٖوسلم کے چچا حضرت عباسؓ کی بیوی کے متعلق بھی تشبیب کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہونا شروع ہوا.دوسری طرف یہودیوں نے علی الاعلان مسلمانوں کے خلاف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں اور مسلمان عورتوں سے تمسخر کرنا شروع کر دیا چنانچہ ایک مسلمان عورت ایک دن بازار میں کسی کام کے لئے گئی.اس کے بعد وہ بنو قینقاع جو ایک یہودی قبیلہ کے لوگ تھے
Page 204
اور سُنار کا کام کرتے تھے اُن میں سے کسی سُنار کے پاس بیٹھ گئی ( بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنا کوئی زیور بننے کے لئے دیا ہوا تھا جب دیر ہو گئی تو وہ اپنے زیور کی تیاری کا حال پوچھنے کے لئے اس یہودی کے پاس آئی ) اُس عورت کے چہرے پر کپڑا جھکا ہوا تھا.یہودی نے اسے کہا کہ اپنا مُنہ کھول دے ( اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا مگر معلوم ہوتا ہے مسلمان عورتوں نے حیا کے اثر کے ماتحت خود بخود اپنے سروں اور چہروں کو ایک حد تک ڈھانکنا شروع کر دیا تھا) عورت نے انکار کیا.اس پر اس شخص نے اُس کی اوڑھنی کو اُس کے تہ بند کے ساتھ تکلے کے ذریعے پر و دیا.جب وہ کھڑی ہوئی تو جھٹکا لگ کر اُس کا کپڑا اُتر گیا اور وہ ننگی ہو گئی اس پر سب یہودی ہنس پڑے.اس عورت نے شور مچا یا.ایک مسلمان جو وہاں سے گزر رہاتھا اُس نے اُس یہودی کا جس نے یہ شرارت کی تھی مقابلہ کیا اور وہ یہودی اس کے ہاتھ سے مارا گیا.اس پر دوسرے یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا.اس واقعہ نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات اور بھی بگڑ گئے.(السیرۃ النبویۃ لابن ہشام امر بنی القینقاع ) یہ ایک انفرادی واقعہ نہیں تھا بلکہ جنگ بدر کے بعد کعب بن اشرف کی شرارتوں کی وجہ سے یہودی قبائل میں اسلام کے خلاف جو جوش پیدا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ کوئی فساد ایسا کریں جس کے نتیجہ میں رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکیں چنانچہ ابن سعد لکھتا ہے فَلَمَّا کَانَتْ وَقْعَۃُ بَدْرٍ اَظْھَرُواا لْبَغْيَ وَ الْحَسَدَ وَ نَبَذُ وا الْعَھْدَ (الطبقات الکبریٰ لابن سعد ذکر غزوة بنی قینقاع) یعنی جب بدر کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہودیوں نے فساد اور بغاوت کرنی شروع کر دی اور عہد کو توڑ دیا.یہ شرارت اس حد تک ترقی کر گئی تھی کہ صحابہؓہر وقت اس خطرہ میں رہتے تھے کہ کوئی شخص دھوکا سے رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم پر حملہ نہ کر دے.چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی طلحہ بن بَراء ؓ شدید بیمار ہوئے.موت کی حالت قریب آ گئی تو وہ رات کا وقت تھا اس پر انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نصیحت کی کہ ان کی وفات کی اطلاع رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو نہ کی جائے اور ان کے رشتہ دار خود ہی انہیں دفن کر دیں تاکہ آپ اُن کے اقرباء کی دلجوئی اور اُن کی تجہیزوتکفین میں شریک ہونے کے لئے ان کے گھر پر تشریف نہ لے آئیں.مبادا اس موقع سے فائدہ اُٹھا کر یہودی لوگ آپ پر حملہ کر دیں.اصل الفاظ ان کے یہ ہیں فَاِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْہِ الْیَہُوْدَ وَاَنْ یُّصَابَ فِیْ سَبَبِیْ یعنی مَیں ڈرتا ہوں کہ یہود آپ پر حملہ نہ کر دیں اور میری وجہ سے آپ کو نقصان نہ پہنچے (الاصابہ فی تمییز الصحابة ذکرطلحۃ بن براءؓ) اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے اُس وقت شرارت اتنی بڑھ چکی تھی کہ مسلمان ہر وقت اِس
Page 205
بات کا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کہیں رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم پر یہودی قاتلانہ حملہ نہ کر دیں.پس رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے ان حالات کے ماتحت بنو قینقاع کے ایک مسلمان عورت کی بے حرمتی کرنے اور ایک مسلمان جو اس کا بدلہ لینے کے لئے گیا تھا اس کے مار دینے کے واقعہ کو ایک انفرادی واقعہ قرار نہیں دیا اور ہرعقلمند انسان اوپر کے واقعات سے یہی استدلال کرے گا کہ یہ انفرادی واقعہ نہیں تھا.سوائے اُن متعصّب عیسائی مؤرخین کے جو اس کو انفرادی واقعہ قرار دے کر بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر چونکہ دونوں طرف سے قتل ہو گیا تھا سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ ختم ہو گیا ہے (لائف آف محمد مصنّفہ میور صفحہ ۲۴۱) باقی ہر منصف مزاج ان تمام حالات کو دیکھ کر کہ ایک طرف مکّہ والوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے اُکسایا جانے لگا.دوسری طرف مسلمان مستورات کے خلاف گندے شعر بنا بناکر علی الاعلان پڑھے جانے لگے.تیسری طرف مسلمان عورتوں کی عزّت پر علی الاعلان حملہ ہونے لگا.چوتھی طرف خود رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی زندگی پر حملہ کرنے کی تیاریاں ہونے لگیں.سمجھ سکتا ہے کہ یہ انفرادی واقعہ نہیں ہو سکتا.آخر رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے بنو قینقاع کو جلاوطنی کی سزا دی اور جو ان جھگڑوں کے اصل بانی تھے یعنی کعب بن اشرف جو اس ساری شرارت کا اُٹھانے والا تھا اور ابورافع جو اس کا خسر اور اس کا حامی اور بنو نضیر قبیلہ کا سردار تھا ان دونوں کے قتل کرنے کا حکم دے دیا.کیونکہ مسلمانوں کے اصل قاتل اور رسول کریم صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے قتل پر اُکسانے کے اصل ذمہ وار وہی دو شخص تھے.کعب بن اشرف اپنی شرارتوں کی وجہ سے اور ابورافع اس کی امداد کرنے کی وجہ سے.عیسائی مؤرخ آج تک شور مچا رہے ہیں کہ ان دونوں شخصوں کو بلاوجہ قتل کر دیاگیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شرارت کے مقابلہ میں جو انہوں نے اُٹھا رکھی تھی اُن کا قتل بالکل بے حقیقت تھا.میرے نزدیک آیت زیر تفسیر میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جو کچھ تم نے کیا تھا وہ تو کیا ہی تھا.اب اس زمانہ میں کہ تم کو دوبار خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا موقع مِل رہا تھا تم نے پھر شرارت پر کمر باندھ لی ہے اور ایک عظیم الشّان نفس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کے متعلق منصوبے کرتے ہو اور کئی قسم کی تدبیریں سوچتے ہو اور پھر ان شرارتوں کی ذمہ داری سے کلیۃً انکار کر بیٹھتے ہو لیکن یاد رکھو یہ تمہاری چال بازیاں کام نہ دیں گی.اﷲ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس قسم کی شرارتوں پر کون اُکسانے والا ہے اور وہ اس پردۂ راز کو کھول کر رکھ دے گا.مطلب یہ ہے کہ اﷲ تعالیٰ جانتا ہے کہ درحقیقت
Page 206
اس شرارت کا بانی مبانی کعب بن اشرف ہے پس اُس کی سزا کے لئے وہ سامان پیدا کر دے گا.اِذْقَتَلْتُمْ نَفْسًامیں قتل کے معنے ارادۂ قتل اور نَفْسًا سے مراد آنحضرت صلعم کی ذات بابرکات یہاں قَتَلْتُمْ نَفْسًا کے الفاظ ہیں جس کے معنے ہیں ’’ تم نے ایک جان کو قتل کیا‘‘ لیکن مَیں نے جو واقعات بتائے ہیں ان سے یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا.اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ قتل کا لفظ قتل کی کوشش یا ارادہ کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آتا ہے.وَ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ١ۖۗ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ.(المؤمن :۲۹) یعنی آل فرعون میں سے ایک ایسا شخص جوموسیٰ پر ایمان لایا تھا.لیکن اپنا ایمان چھپا کر رکھتا تھا اس نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے کہا.کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اﷲ میرا ربّ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بڑے بڑے نشان لایا ہے.ظاہر ہے کہ یہاں ارادۂ قتل کے معنوں میں قتل کا لفظ استعمال ہوا ہے پس آیت زیر تفسیر میں بھی قَتَلْتُمْ نَفْسًا سے مراد یہ معنی کرنے جائز ہیں کہ تم نے ایک عظیم الشّان انسان کے قتل کا ارادہ کیا اور ایسا پختہ ارادہ کیا اور عملی طور پر اس کے لئے ایسے سامان پیدا کرنے شروع کر دیئے کہ یُوں کہنا چاہیے گویا تم نے اپنی طرف سے اُسے قتل کر ہی دیا.مگر اس کے علاوہ ایک مسلمان کی جان بھی ان یہودیوں نے لی تھی گو وہ مسلمان ایک معمولی حیثیت کا آدمی تھا مگر چونکہ اس ساری شرارت کی غرض اصل میں یہ تھی کہ کسی طرح رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو قتل کرنے کا موقع نکالا جائے اس لئے اس کا قتل بھی محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کا قتل کہلائے گا.پس قَتَلْتُمْ نَفْسًا سےاس شخص کا قتل بھی مراد لیا جا سکتا ہے جسے بنو قینقاع نے قتل کیا اور اس کی عظمت اس بناء پر سمجھی جائے گی کہ اس کا قتل در حقیقت رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی نیابت میں تھا.یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہودی لوگ تو تھوڑے تھے.ان کے دلوں میں اتنا جوش کہاں پیدا ہو سکتا تھا کیونکہ گو یہودی تعداد میں تھوڑے تھے لیکن انہیں مدینہ کے لوگوں کی امداد کا عمومًا اور منافقین کا خصوصًا بھروسہ تھا کیونکہ وہ ان کے سالہا سال سے حلیف چلے آ رہے تھے.پھر مکّہ کے لوگ بھی ان کو اُکسارہے تھے.علاوہ ازیں وہ اپنے آپ کو زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ منظّم سمجھتے تھے.چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع نے مجلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ’’ یَا مُحَمَّدُ اِنَّکَ تَرٰی أَنَّـا قَوْمُکَ لَا یَغُرَّنَّکَ اَنَّکَ لَقِیْتَ قَوْمًا لَا عِلْمَ لَھُمْ بِالْحَرْبِ فَاَصَبْتَ مِنْھُمْ فُرْصَۃً، اِنَّا وَ اللہِ لَئِنْ حَارَبْنَاکَ لَتَعْلَمَنَّ اَنَّا نَحْنُ النَّاسُ.‘‘ اے محمد تم شاید چند قریش کو قتل
Page 207
امر پر ہے کہ خدا رحمٰن نہیں.اگر وہ رحمٰن ہے تو پھر وہ گناہ بھی بخش سکتا ہے لیکن عیسائیت کہتی ہے کہ وہ کسی کو بخش نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے گویا جو کام اس دنیا میں ہرانسان کرتا ہے اور جس کام کے کرنے پر انسان کی تعریف کی جاتی ہے نہ کہ مذمت وہ خدا نہیں کر سکتا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا رحم تقاضا کرتا تھا کہ وہ اپنے بندوں کو بخشے.پس اس نے اپنے بیٹے کو دنیامیں بھیجا اور وہ لوگوں کے گناہوں کے بدلہ میں پھانسی پر لٹک گیا.اب چونکہ تمام گناہ خود اس نے اٹھا لئے ہیں اور وہ لوگوں کے گناہوں کے بدلہ میں کفار ہ ہو گیا اس لئے لوگوں کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں وہ مسیح ؑ پر ایمان لانے کے نتیجہ میں ہی نجات پا جائیں گے.غرض عیسائیت کی ساری بنیاد ہی اس امر پر ہے کہ خدا رحمٰن نہیں.لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو انہوں نے کہا اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا.اگر تو تقی ہے تو میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں رحمٰن کے معنے ہیں وہ ہستی ہے جو بغیر کسی عمل کے انسان کو اپنی نعمتوں سے متمتع فرماتی ہے.یہ ایک رؤیا کا نظارہ تھا جو حضرت مریم نے دیکھا.اور رؤیا میں جب انسان کوئی خطرہ کی بات دیکھتاہے.تو جس طرح مادی دنیا میں وہ گھبراتا ہے اسی طرح خواب میں بھی گھبراتا ہے.مثلاً اگر تم رؤیا میں دیکھو کہ تم اوپر سے گرنے لگے ہو توتم ڈرو گے.اگر تم دیکھوکہ تم ڈوبنے لگے ہو تو تم گھبرائو گے.اسی طرح خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ وہ مرنے لگا ہے تو وہ خوش نہیں ہو گا.بلکہ غمزدہ ہوگا.پس بے شک یہ ایک کشفی نظارہ تھا جو انہوں نے دیکھا.لیکن ظاہر میں جو بات ناپسندیدہ ہو وہ اگر کشف میں پیش آئے تو انسان ناپسندیدگی کا ہی اظہار کرے گا.اسی وجہ سے حضرت مریم نے جب فرشتہ کو انسانی صورت میں اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو وہ گھبرا گئیں اور انہوں نے کہا کہ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا.ان الفاظ میں ان کے قلب کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت مریم اس نظارہ کو دیکھ کر اس قدر گھبرائیں کہ انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تجھ میں تقویٰ پایا جاتا ہے.تو میں خدائے رحمٰن سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے تیرے شر سے بچا لے.رحمٰن کے معنے ہیں وہ ہستی جو بے محنت اور کوشش کے اپنافضل نازل کرتی ہے.گویا وہ اس قدر گھبرا گئیں کہ انہوں نے کہا خدایا تو میرے عمل کو نہ دیکھ کہ میں نے تیری رضاء کے لئے کچھ کیا ہے یا نہیں میں تجھے رحمانیت کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ تو مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ.اگر اس میں رحیمیت کا واسطہ ہوتا تو اس کے معنے یہ ہوتے کہ خدایا کچھ عمل میں نے بھی کئے ہوئے ہیں ان کی جزاء کے طورپر میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھ پر رحم فرما لیکن وہ رحیمیت کا واسطہ نہیں دیتیں.وہ اپنے انتہائی درد اور کرب کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئی رحمانیت کا واسطہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں خدایا میرا کوئی عمل نہیں مجھ بے عمل پر ہی
Page 208
ایسے سامان ضرور کرے گا کہ جن سے تمہارے یہ قومی ارادے ایک دن پوری طرح ننگے ہو جائیں گے.ان دوسرے معنوں کی رو سے وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ کاجملہ یہودیوں کے اندرونہ کی وقتی پردہ دری پر دلالت کرنے کے علاوہ ایک ضمنی جملہ کے طور پر آئندہ کے لئے ایک پیشگوئی بھی قرار دیا جائے گا.اگر کہا جائے کہ پہلے معنوں پر تو یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ چونکہ ان کاظہور بعد کے زمانہ سے متعلق ہے اس لئے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ سے اس کا جوڑ نہیں رہتا لیکن یہاں بھی وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ کوایک پیشگوئی قرار دیا گیا ہے جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے معنوں میں فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ والی آیت کا تعلق بھی مستقبل بعید سے بتایا جاتا ہے لیکن اس جگہ صرف وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَکو ضمنی جملہ اور پیشگوئی بتایا گیا ہے.فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ کوحال ہی سے متعلق بتایا گیا ہے پس ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ کا تعلق فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُسے قائم ہے اور کوئی اختلاف معنوں میں پیدا نہیں ہوتا.پھر فرماتا ہے.فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا یعنی محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے قتل کا ارادہ کرنے پر یا ایک مسلمان کو اس غرض کے پورا کرنے کے لئے قتل کر دینے پر ہم نے کہا.اِضْرِبُوْهُ قاتل کو مارو بِبَعْضِهَا اس کے بعض کے سبب سے.اس جملہ کے بعض حصّے تشریح طلب ہیں.فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ میں ضرب کے معنے تلوار سے مارنے کے اوّل ضَرَبَکے عام معنے پیٹنے کے ہوتے ہیں لیکن اس جگہ پر مَیں نے قتل کے معنے لئے ہیں چنانچہ لغت میں لکھا ہے ضَرَبَہٗ بِیَدِہٖ وَ بِالْعَصَا وَ نَحْوَھَا: اَصَا بَہٗ وَ صَدَ مَہٗ بِھَا یعنی اپنے ہاتھ سے یا سونٹے سے یا ایسی ہی کسی اور چیز سے اُسے چھوا یا زور سے ٹکرایا یعنی مارا.لیکن جس طرح ضَرَبَہٗ بِیَدِہٖ یا ضَرَبَہٗ بِالْعَصَا کہنے سے مارا کے معنے نکلتے ہیں اسی طرح لغت میں لکھا ہے کہ جب ضَرَبَہٗ بِالسَّیْفِکے الفاظ استعمال ہوں تو اس کے معنے ہوتے ہیں اَوْقَعَ بِہٖ (اقرب) تلوار سے اس پر حملہ کیا.پس گو عام استعمال کے مطابق ضَرَبَ کے معنے مارنے کے ہی ہوتے ہیں لیکن جیسا کہ مَیں نے لغت سے اوپر بتایا ہے جب ضَرَبَ بِالسَّیْفِ مراد ہو تو اس کے معنے قاتلانہ حملہ یا قتل کرنے کے ہوتے ہیں.چونکہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے کعب بن اشرف کے مارنے پر جو اِس فتنہ کا بانی مبانی تھا ایک صحابی کو مقرر کیا تھا اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو شخص مارنے کے لئے جائے وہ قتل پر قابوبھی پا لے.وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتا ہے اس لئے موقع کی مناسبت سے اِضْرِبُوْہٗ کے الفاظ استعمال کئے ( جن کا متعلق بالسیف محذوف ہے) اور مراد یہ ہے کہ اس پر تلوار سے حملہ کرو.قتل کا حکم درحقیقت ایسے شخص کو ہی دیا جا سکتا ہے جو قتل پر قادر ہو جیسے حکومت کے کسی نمائندہ کو حکومت کے کسی فرد کے قتل کرنے کا حکم دیا جائے مگر کعب بن اشرف اسلامی نظامِ حکومت کے اس طرح تابع نہیں تھا پس اس وجہ سے
Page 209
اِضْرِبُوْہُ کے الفاظ استعمال کئے گئے اور مراد یہ ہے کہ اِضْرِ بُوْہُ بِالسَّیْف اُس پر تلوار سے حملہ کرو.بِبَعْضِہَا میں بَاء تعلیل کے معنے دیتی ہے اور مراد یہ ہے کہ اس کے بعض کے سبب سے یا بعض کی وجہ سے.اور بعض کے بعد اِثْمٌ یعنی گناہ یا ایسا ہی کوئی اور لفظ محذوف ہے جو عربی قاعدہ کے رُو سے اکثر محذوف ہو جایا کرتا ہے.پس سارے جملہ کے معنے یہ ہوئے کہ ہم نے کہا قاتل پر اس کے گناہ کے بعض حصّے کی وجہ سے تلوار کے ساتھ حملہ کرو.بعض حصّہ اس لئے کہا گیا ہے کہ کعب بن اشرف کا گناہ صرف اس دنیا کی سزا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا اور اس کے گناہ کی سزا کو اُس کا قتل کیا جانا ڈھانپ نہیں سکتا تھا بلکہ وہ اس بات کا مستحق تھا کہ اگلے جہان میں بھی اُس کو خالص خدائی عذاب میں مبتلا کیا جائے.چنانچہ قرآن کریم میں اﷲ تعالیٰ قاتلوں کے متعلق فرماتا ہے وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا ( النِّسَآء :۹۴)جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار دے اس کی سزا جہنّم ہے جس میں وہ دیر تک بستا چلا جائے گا.لیکن قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ ایسے شخص کی یہ بھی سزا ہے کہ اُسے قتل کیا جائے پس معلوم ہوا کہ قاتل کو دو۲ سزائیں ملتی ہیں.ایک اس دنیا میں قتل کے ذریعہ سے اور ایک اگلے جہان میں جہنّم میں ڈال کر.پس بِبَعْضِ اِثْمِھَا سے مراد یہ ہوئی کہ تم اپنے حصّہ کی سزا اسے قتل کے ذریعہ سے دے لو.دوسرے حصّہ کی سزا ہم خود اسے اُس کی موت کے بعد دیں گے.فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَامیں بِبَعْضِہَا سے مراد یہ جو مَیں نے بتایا ہے کہ بِبَعْضِہَا میں بَاء حرف تعلیل کے طور پر استعمال ہوئی ہے ان معنوں میں باء کے استعمال کی مثالیں قرآن کریم میں بھی ملتی ہیں اﷲتعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ (المآئدۃ:۱۴)ہم نے ان کے عہد توڑ دینے کے سبب سے اُن پر لعنت کی اور یہ جو میں نے لکھا ہے کہ ھَا کا مضاف یعنی اِثْمٌ کا لفظ حذف کیا گیا ہے اس کا استعمال بھی قرآن کریم میں موجود ہے.اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (المآ ئدة:۴)تم پر مُردہ حرام کیا گیا ہے حالانکہ مردہ حرام نہیں ہوتا.مُردے کا کھانا حرام ہوتا ہے پس اصل الفاظ یہ ہیں حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اَکْلُ الْمَیْتَۃِ تم پر مُردے کا کھانا حرام کیا گیا ہے.اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَ سْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ( یوسف :۸۳)تم اس بستی سے پوچھو جس میں ہم تھے اور عیرسے پوچھو جن کے ساتھ واپس آئے ہیں حالانکہ بستی مکانوں کے مجموعہ کا نام ہے.عِیْرکے معنے گدھوں کے ہیں.نہ کوئی مکانوں سے پوچھا کرتا ہے اور نہ گدھوں سے پوچھتا ہے.پس بستی سے بستی والے اور گدھوں سے گدھوں والے مراد ہیں.اور مالک کا لفظ یا صاحب کا لفظ جو قریہ اور عِیر کی طرف مضاف تھا اسے حذف کر دیا گیا ہے اور مراد یہ ہے کہ اِسْئَلُوْا اَھْلَ الْقَرْیَۃِ وَ اَصْحَابَ الْعِیْرِ.
Page 210
اس کے بعد فرماتا ہے كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى.اﷲ تعالیٰ اسی طرح مُردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی انبیاء کی جماعتوں کو لوگ تباہ کرنا چاہتے ہیں اور نبیوں کو قتل کر کے اُن کو مٹانا چاہتے ہیں مگر جس قسم کے انبیاء کو قتل سے محفوظ رکھنے کا خدا تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ ان نبیوں کو دشمنوں کے حملوں سے ضرور بچاتا ہے اور جب دشمن اُنہیں اپنی طرف سے مار چکا ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کے ذریعہ سے گویا اُن کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے.یہ اﷲ تعالیٰ کی سنّت ہے کہ سلسلۂ روحانیہ کے پہلے اور آخری نبی کے قتل پر اُن کے دشمن کبھی تسلّط نہیں پاتے کیونکہ قومی احیاء کا حقیقی نمونہ ان ہی دو نبیوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے جیسے کہ موسوی سلسلہ میں پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور آخری حضرت مسیح علیہ السلام تھے جو احیاء بنی اسرائیل کا ان دو نبیوں کے ذریعہ سے ہوا درمیانی انبیاء کا کام ان کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا.ان انبیاء کو اﷲ تعالیٰ ہر حالت میں دشمنوں کے حملوں سے بچاتا ہے اسی طرف كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى میںاشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ جن کو خدا تعالیٰ موت سے بچانا چاہے اُنہیں کوئی مارنے پر قادر نہیں ہو سکتا دوسرے اس احیاء کی طرف بھی اشارہ ہے جو ان انبیاء کے ذریعہ سے دنیا میں ہوتا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ کسی سِلسلہ کے اوّل اور آخری نبی کو مارنا چاہتے ہیں اﷲ تعالیٰ انہیں ضرور ہلاک کرتا ہے کیونکہ اگر وہ ہلاک نہ کئے جائیں تو دنیا زندہ نہیں ہو سکتی پس ان کی ہلاکت پر اعتراض کرنا حماقت ہے اعتراض تو اس صورت میں ہوتا کہ ان انبیاء کے ایسے دشمن جو انہیں ہلاک کرنا چاہیں خود ہلاک نہ ہو جائیں.وَ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ سے یہ بتایا کہ اس قسم کے نشانوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کی شرارتوں سے روکا جائے اور نیکی کی طرف لایا جائے.یہود کو سزائیں ملیں اور رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم اور ان کی جماعت کو خدا تعالیٰ نے ہر قسم کے ظاہر اور خفیہ حملوں سے محفوظ رکھا.اس میں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں ایک بڑا نشان تھا چنانچہ کچھ یہودی مسلمان بھی ہو گئے مگر قوم کے بیشتر حصّہ نے ان نشانوں سے کوئی فائدہ نہ اُٹھایا.غرض ان دونوں آیتوں میں جو اوپر گزریں اُس عظیم الشان اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جو عیسائی اور یہودی آج تک رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم پر کرتے چلے آتے ہیں کہ آپ نے کیوں کعب بن اشرف اور ابورافع سلام بن ابی الحقیق کو قتل کرایا اور بتایا ہے کہ ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بعض مسلمان مارے گئے بلکہ رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے قتل کرنے کی سازشیں بھی ہوئیں اور کسی جماعت کے امام یا کسی ملک کے بادشاہ کے قتل کا ارادہ درحقیقت اُس ساری قوم کے قتل کے برابر ہوتا ہے.یورپ کے لوگوں نے بھی ایسے جرم کو ایک
Page 211
خاص نام ہائی ٹریزن(HIGH TREASON) کا دیا ہے اور ’’ ہائی ٹریزن‘‘ کے جرم میں جن لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ اُن کا جُرم قتل کے جرم پر ہی مشتمل ہو.آجکل بھی جب کہ دوسری جنگ ِ عالم جاری ہے.معمولی جاسوسیوں کے جرم میں لوگوں کو پھانسیاں ملتی ہیں.عیسائی اور یہودی یہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور ابورافع بن ابی الحقیق کو کیوں مروا دیا گیا مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ اشخاص محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے قتل کرنے کے فکر میں تھے اور اس کے لئے لوگوں کو اُکساتے تھے.کیا دنیا کی کوئی بھی حکومت ہے جو ایسے آدمی کو قتل نہ کرے گی جو اُن کی حکومت کے افسر یا رئیس کو قتل کروانے کے لئے باقاعدہ سازشیں کر رہا ہو.اس صورت میں وہی حکومت اس بات سے اغماض کر سکتی ہے جو خود بھی اپنے سردار کی قیمت کو نہ سمجھتی ہو اور اُس کے مارے جانے میں مُلک کا کوئی زیادہ حرج نہ پاتی ہو مگر صحابہؓتو رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے عاشق تھے.اُن کی محبت کا اندازہ اسی مذکورہ بالا واقعہ سے ہی کیا جا سکتا ہے جس میں ذکر ہے کہ جب ایک صحابی رات کے وقت فوت ہونے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے مرنے کی رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کو خبر نہ دی جائے تا ایسا نہ ہو کہ آپ ہمدردی کی وجہ سے رات کے وقت میرے مکان پر آنا چاہیں اور یہودی آپ کو قتل کر دیں.صحابہ ؓ کے دل میں رسول کریم صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے جنازہ پڑھانے کی جو قیمت تھی اُس کا پورا اندازہ عیسائی اور یہودی نہیں لگا سکتے لیکن پھر بھی اگر وہ تعصّب سے خالی ہو کر اُس صحابی کی اس قربانی پر غور کریں تو وہ سمجھ سکیں گے کہ رسول کریم صلی اﷲعلیہ و آلہٖ وسلم کی جان کو یہودیوں سے اُس وقت بہت ہی بڑا خطرہ تھا.اتنا بڑا خطرہ کہ جس کے لئے اس صحابی نے اس نعمت کو قربان کر دیا.جو نعمت یقیناً اس کو اپنی جائیداد اور اپنے بال بچوں کی جان سے زیادہ پیاری تھی.اگر خطرہ حقیقی نہ ہوتا اور بہت سخت نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ صحابی اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم نہ کرتا کہ رسول کریم صلے اﷲعلیہ و آلہٖ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں.ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ پتھروں کی طرح بلکہ اَشَدُّ قَسْوَةً١ؕ وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ (ان سے بھی) زیادہ سخت ہیں اور پتھروںمیں سے تو یقیناً بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے
Page 212
الْاَنْهٰرُ١ؕ وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ١ؕ وَ دریا بہتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے (بھی) ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ١ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اور ان (یعنی دلوں ) میں سے (بھی) بعض ایسےہیں کہ اللہ کے ڈر سے (معافی مانگتے ہوئے)گر جاتے ہیں عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۰۰۷۵ اور جو (کچھ )تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے.حَلّ لُغَات.قَسَتْ.قَسَا سے مؤنث کا صیغہ ہے اور قَسَاقَلْبُہٗ (یَقْسُوْ قَسْوًا وَ قَسَاوَۃً) کے معنی ہیں صَلُبَ وَ غَلَـظَ اس کا دِل سخت ہو گیا اور جب لفظ قَسَا درہم کے متعلق استعمال کریں اور کہیں قَسَا الدِّرْھَمُ تو اس کے معنے ہوتے ہیں زَافَ کہ سکّہ خالص دھات کا نہیں ہے اس کے اندر مِلاوٹ کر دی گئی ہے (اقرب) اَلْقَسْوَۃُ.اَلصَّلَا بَۃُ فِیْ کُلِّ شَیْ ءٍ یعنی ہر چیز کی سختی کو قَسْوَۃٌ سے تعبیر کرتے ہیں اور جب قَسْوَۃٌ کا لفظ قلب کے لئے استعمال کریں تو اس کے معنے ہوںگے.ذِھَابُ اللِّیْنِ وَالرَّحْمَۃِ وَالْخُشُوْعِ دل سے نرمی، شفقت اور خشوع کا نکل جانا.(لسان)پس قَسَتْ قُلُوْبُکُمْ کے معنے ہوں گے کہ (۱)تمہارے دِل سخت ہو گئے.(۲) تمہارے دل نرمی، شفقت اور خشوع سے خالی ہو گئے.اَلْحِجَارَۃُ.اَلْـحَجَرُ کی جمع ہے اور اَلْـحَجَرُ کے معنی ہیں اَلْجَوْھَرُالصُّلْبُ پتھر (مفردات) اس کی جمع اَحْجَارٌ بھی آتی ہے اور حَجَرَانِ سونے اور چاندی کو کہتے ہیں.(اقرب) یَتَفَجَّرُ.یَتَفَجَّرُ تَفَجَّرَ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور تَفَجَّرَالْمَاءُ کے معنی سَالَ الْمَاءُ وَ جَرٰی پانی بہہ پڑا(اقرب) پس یَتَفَجَّرُ کے معنے ہوں گے بہہ پڑتے ہیں.اَلْاَنْھَارُ.اَلنَّھْرُ کی جمع ہے او ر اَلنَّھْرُ کے معنے ہیں مَـجْرَی الْمَاءِ الْفَائِضِ بہنے والے پانی کے چلنے کی جگہ.وَجَعَلَ اللّٰہُ تَعَالٰی ذٰلِکَ مَثَـلًا لِّمَایُدِرُّمِنْ فَیْضِہٖ وَفَضْلِہٖ فِی الْجَنَّۃِ عَلَی النَّاسِ قَالَ.اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ(القمر:۵۵) اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے بطور مثال کے اپنے اس فیض اور فضل کو جو اس کے بندوں پر جنت میں بکثرت نازل ہو گا بیان کیا ہے.جیسے کہ فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ نَهَرٍ کہ متقی باغات اور نہروں
Page 213
میں ہوں گے وَالنَّھَرُ.اَلسَّعَۃُ تَشْبِیْھًا بِنَھْرِ المَآءِ.نَھَر کے معنی وسعت کے ہیں.نہر کا پانی چونکہ وسیع ہوتا ہے اس لئے اس کو اس پر قیاس کر لیا.چنانچہ کہتے ہیں نَھْرٌ نَھِرٌ اَیْ کَثِیْرُ الْمَآءِ بہت پانی والا دریا.(مفردات) یَشَّقَّقُ.اصل میں یَتَشَقَّقُ ( باب تفعّل سے مضارع واحد غائب کا صیغہ ) تھا.ت کو شین میں اِدغام کیا گیا.اس کی ثلاثی شَقَّ ( یَشُقُّ) ہے.شَقَّ الشَّیْءَ (متعدی ) کے معنے ہوتے ہیں صَدَعَہٗ وَفَرَّقَہٗ کہ کسی چیز کو پھاڑ دیا اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیا.تَشَقَّقَ ( باب تفعّل میں) اَلْحَطَبُ کے معنے ہیں کہ ( کسی نے) لکڑی (کو پھاڑا اور وہ) پھٹ گئی.آیت ھٰذا میں یَشَّقَّقُ کے معنے ہوں گے ( بعض دل) پھٹ جاتے ہیں.(اقرب) یَھْبِطُ.ھَبَطَ سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ھَبَطَ مِنَ الْخَشْیَۃِ کے معنی ہیں تَضَاءَ لَ وَخَشَعَ یعنی ڈر کی وجہ سے کمزور اور چھوٹا ہو گیا اور اس نے عاجزی اختیار کی ( اقرب) اَلْھَبُوْطُ اَ لْاِنْحِدَارُ اوپر سے نیچے کی طرف گرنا.( مفردات) ھَبَطَہُ (یَھْبُطُ ھَبْطًا) مِنَ الْجَبَلِ کے معنے ہیں اَنْزَلَہٗ اس کو پہاڑ سے اُتارا.ھَبَطَ بَلَدًا کَذَا.دَخَلَہٗ کسی شہر میں داخل ہوا (یہ متعدّی بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ ھَبَطَہٗ بَلَدًا کَذَا کے معنے ہوں گے اَدْخَلَہٗ اس کو فلاں شہر میں داخل کیا) ھَبَطَ السُّوْقَ: اَتَاھَا بازار میں آیا.ھَبَطَ فُـلَانٌ مِنَ الْجَبَلِ (یَھْبُطُ وَ یَھْبِطُ ھُبُوْطًا) نَزَلَ پہاڑ سے اُترا.ھَبَطَ الْوَادِیَ : نَزَلَہٗ وادی میں اُترا.ھَبَطَ مِنْ مَوْضِعٍ اِلٰی مَوْضِعٍ آخَرَ: اِنْتَقَل ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا (اقرب) پس اِھْبِطُوْاکے معنے ہوں گے(۱) اپنی جائے قیام کو چھوڑ کر کسی اور جگہ قیام پذیر ہو جائو (۲) نکل جائو.پس یَھْبِطُ مِنْ خَشْیَۃِ اللہِ کے معنے ہوں گے کہ(۱) ان دلوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ ( معافی مانگتے ہوئے) اﷲ کے ڈر سے گر جاتے ہیں (۲) اﷲ کے ڈر کی وجہ سے عاجزی اختیار کرتے ہیں.خَشْیَۃٌ.خَشِیَہٗ (یَخْشَاہُ خَشْیَۃً) کے معنے ہیں خَافَہٗ وَ اتَّقَاہُ کسی چیز سے ڈر ااور اس سے خوف محسوس کیا.اَلْخَشْیَۃُ کے معنے ہیں اَلْخَوْفُ خوف.(اقرب) کلیات ابی البقا میں ہے اَلْخَشْیَۃُ اَشَدُّ مِنَ الْخَوْفِ وَالْخَشْیَۃُ تَکُوْنُ مِنْ عَظْمَۃِ الْمَخْشِیِّ وَ الْخَوْفُ یَکُوْنُ مِنْ ضُعْفِ الْخَآئِفِ ( بحوالہ اقرب) یعنی لفظ خشیت میں ڈر کا مفہوم لفظ خوف کی نسبت زیادہ پایا جاتا ہے نیز خشیت اور خوف میں ایک یہ بھی فرق ہے کہ خشیت میں اس ڈر کے معنے پائے جاتے ہیں جو مَخْشَی ( یعنی جس ذات سے ڈرا جائے) کی عظمت کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے اور خوف میں اس ڈر کا مفہوم پایا جاتا ہے جو ڈرنے والے کی اپنی کمزوری پر دلالت کرتا ہے.امام راغب لکھتے ہیں اَلْخَشْیَۃُ
Page 214
خَوْفٌ یَشُوْبُہٗ تَعْظِیْمٌ یعنی خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں اس شخص کی بزرگی اور تعظیم کا خیال بھی شامِل ہو جس سے خشیت کی جائے.پھر لکھتے ہیں وَاَکْثَرُ مَا یَکُوْنُ ذٰلِکَ عَنْ عِلْمٍ بِمَا یُخشٰی مِنْہُ اور لفظ خشیت کا اکثر استعمال اس جگہ ہوتا ہے جہاں خوف کی وجہ کا بھی علم ہو وَلِذٰلِکَ خُصَّ الْعُلَمَاءُ بِھَا فِی قَوْلِہٖ ’’ اِنَّمَا یَخْشَی اللہَ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَمَاءُ (الفاطر:۲۹) یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی خشیت اس کے عالم بندوں کے دل میں ہوتی ہے ورنہ خوف تو عام لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے.(مفردات) بِغَافِل.غَافِلٌ غَفَلَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور غَفَلَ عَنْہُ غَفْلَۃٌ کے معنے ہیں تَرَکَہٗ وَسَھٰی عَنْہُ کسی چیز ( پر مداومت) کو چھوڑ دیا اور اس کو بھول گیا.نیز کہتے ہیں غَفَلَ الشَّیْءَ اور معنے یہ ہوتے ہیں سَتَرَہُ یعنی فلاں چیز پر پردہ ڈال کر اُس کو ڈھانپ دیا (اقرب) اَلْغَفْلَۃُ سَھْوٌ یَعْتَرِی الْاِنْسَانَ مِنْ قِلَّۃِ التَّحَفُّظِ وَ التَّیَقُّظِ یعنی قوتِ حافظہ اور دماغی بیداری کے کم ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو بھلادینا غفلت کہلاتا ہے ( لسان) اہلِ عرب کہتے ہیں اَنْتَ غَافِلٌ اور مطلب یہ ہوتا ہے لَا تَعْنِیْ بِشَیْءٍ کہ تُو تو کسی شے کی طرف توجہ نہیں دیتا ( لسان) ابوالبقاء کہتے ہیں اَلغَفْلَۃُ ھُوَالذُّ ھُوْلُ عَنِ الشَّیْءِ کہ کسی چیز کو بھلا دینا غفلت کہلاتا ہے ( تاج ) غَافِلٌ کی جمع غَافِلُوْنَ ، غُفُوْلٌ اور غُفَّلٌ آتی ہے.(اقرب)پس وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ کے معنے ہوں گے کہ(۱) اﷲ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہو جائے (۲) تمہارے اعمال پر پردہ ہی ڈالتا چلا جائے (۳)تمہارے اعمال کو بھلا دے اور اُن کا کوئی نتیجہ نہ نکالے(۴) تمہارے اعمال کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹالے.تفسیر.ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُکُمْ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس آیت میں ثُمَّ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس کا مضمون پہلی آیتوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مراد یہ ہے کہ پہلے نشانات کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی مگر تمہارے دل اور بھی زیادہ سخت ہو گئے چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ کعب بن اشرف اور ابورافع بن ابی الحقیق کے قتل کئے جانے کے باوجود اور بنوقینقاع کے مدینہ سے نکالے جانے کے باوجود یہود کے دوسرے دو قبیلوں یعنی بنو نضیر اوربنو قر یظہ شرارتوں میں اور بھی بڑھ گئے.فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً.فرماتا ہے وہ دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ سختی میں اُن سے بھی زیادہ.پتھر کے ساتھ دل کی سختی کی مشابہت قریبًاہر زبان میں دی جاتی ہے یہاں بھی وہی مشابہت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ خدائی باتوں کو قبول کرنے کے لئے اُن کے دل تیار نہیں ہوتے حتّٰی کہ پتھر میں بھی کوئی نرمی ہوتی ہے مگر ان کے دلوں میں کوئی نرمی نہیں.
Page 215
اَوْ کا لفظ اس جگہ پر شک کے لئے نہیں آیا بلکہ مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں اور کچھ لوگوں کے دل اُن سے بھی سخت ہیں.وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُپھر فرماتا ہے ہم نے جو یہ کہا کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ پتھروں میں سے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے دباؤ سے پھٹ جاتے ہیں اور اُن کے بیچ میں سے نہریں بہنے لگ جاتی ہیں چنانچہ یہ نظارے کثرت سے پہاڑوں میں نظر آتے ہیں کہ اونچی برفوں سے بہنے والے زمین دوز پانیوں کے دباؤ سے کئی جگہ پر پتھریلی زمینیں شق ہو جاتی ہیں اور اُن میں سے پانی پہنے لگتا ہے.مگر یہودی لوگ کچھ ایسے سخت دل ہو گئے کہ خدا کے کلام کی نہر جاری ہوئی مگر اُن کے دلوں نے اس کو کوئی راستہ نہ دیا اور خدا تعالیٰ کی آیات کا ظَاہِرًاوَ بَاطِنًا انکار ہی کرتے چلے گئے.وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ.اور ان میں سے ( یعنی پتھروں میں سے ) بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو اُن میں سے پانی نکلتا ہے یعنی کوئی بڑا چشمہ تو اُن میں سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا تھوڑا پانی اُن میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے گویا اس جگہ پر اس بات کی مثال دی ہے کہ بعض لوگوں سے کم نیکی کا ظہور ہوتا ہے اور بعض لوگوں سے زیادہ نیکی کا ظہور ہوتا ہے.بعض لوگ تو اُن پتھروں کے مشابہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے سے بڑے بڑے چشمے بہتے ہیں یعنی شروع میں تو وہ صداقت کا مقابلہ کرتے ہیں مگر آخر صداقت کے اثر کو قبول کر لیتے اور اسے رستہ دے دیتے ہیں اور اس حد تک اُس سے اثر پذیر ہوتے ہیں کہ صداقت بڑے زور سے اُن میں سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں تو صداقت کا مقابلہ کرتے ہیں مگر آخر اُسے رستہ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن اُن کا تأ ثر زیادہ شدید نہیں ہوتا.صداقت اُن سے نکلتی ہے مگر کم مقدار میں.لیکن فرماتا ہے یہود میں سے اکثر لوگ اس درجہ کے بھی نہیں ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہیں.وہ کسی صورت میں بھی خدائی صداقتوں کو نکلنے کے لئے رستہ نہیں دیتے.نہ چھوٹا رستہ نہ بڑا.پھر فرماتا ہے وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ اس فقرہ کے دو طرح معنے کئے جا سکتے ہیں.ایک تو اس طرح کہ ھَا کی ضمیر پتھروں کی طرف پھیری جائے اور معنے یہ کئے جائیں کہ پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خشیت اﷲ سے گر جاتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں کہ پتھروں میں عقل اور امتیاز کا مادہ پایا جاتا ہے اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے خوف کو اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح کہ انسان محسوس کرتا ہے بلکہ اس جگہ پر خشیت کا مضاف محذوف ہے (تصریح جلد دوم) اور مراد یہ ہے کہ خشیت اﷲ پیدا کرنے کے اسباب سے گر جاتے ہیں.جیسے آندھیاں ہیں،
Page 216
زلزلے ہیں، سیلاب ہیں، گرنے والی بجلیاں ہیں، یہ سب چیزیں خشیت اﷲپیدا کرنے کا موجب ہوتی ہیں اور ان چیزوں سے پتھر بھی گرتے ہیں.پس مطلب یہ ہوا کہ سیلاب آتے ہیں تو پتھر بھی ان سے متأثر ہو جاتے ہیں.آندھیاں آتی ہیں تو پتھر بھی ان سے متأثر ہو جاتے ہیں.زلزلے آتے اور بجلیاں گرتی ہیں تو بھی پتھر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن زمینی اور آسمانی انقلابات متواتر اور شدّت کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں مگر ان سنگ دل اور متعصّب یہودیوں کے دلوں میں کچھ بھی خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا اور ان کے دل خدا تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہی نہیں.دوسرے معنی اس کے اس طرح پر کئے جا سکتے ہیں کہ گو خشیت کے معنے ڈرنے کے ہیں لیکن کبھی ثلاثی مصدر رباعی کے قائم مقام کے طورپر بھی استعمال ہو جاتا ہے ( بحرِ محیط زیر آیت ھذا) اسی طرح خشیت اس جگہ اِخْشَاءٌ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور معنے یہ ہیں کہ اﷲ تعالیٰ سے ڈرانے والی چیزوں کے سبب سے ( جیسے آندھیاں، سیلاب، بجلیاں اور زلزلے ہیں ) بعض پتھر گر جاتے ہیں.اس تشریح کے لحاظ سے بھی معنے وہی رہیں گے جو پہلے بیان ہوئے ہیں.صرف نحوی ترکیب میں فرق پڑ جائے گا یعنی پہلے معنی اس بنیاد پر کئے گئے تھے کہ یہاں مضاف حذف ہو گیا ہے اور دوسری تشریح کے رو سے وہی معنے اس لحاظ سے کئے گئے ہیں کہ خشیت کا لفظ ہی اِخْشَاءٌ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے.ان دوسرے معنوں کے کرتے وقت یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گاکہ اس جگہ مصدر بمعنے اسم فاعل استعمال ہوا ہے جیسے کہتے ہیں زَیْدٌ عَدْلٌ اور مراد یہ ہوتا ہے کہ زَیْدٌ عَادِلٌ.اور یہ سمجھا جائے گا کہ خشیت بمعنے اِخْشَاءٌ استعمال ہوا ہے اور اِخْشَاءٌ مَـخْشِیٌّ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے.(مصدر بمعنی اسم فاعل و مفعول استعمال ہونے کے لئے دیکھو رضی بحث مصدر) تیسرے معنی اس آیت کے یوں کئے جا سکتے ہیں کہ ھَا کی ضمیر قلوب کی طرف پھیری جائے اور یوں معنی کئے جائیں کہ دلوں میں سے یقیناً بعض ایسے ہوتے ہیں جو اﷲ تعالیٰ کی خشیت سے گر جاتے ہیں.قُلُوبٌ کا لفظ پہلے آچکا ہے اور اس کی طرف ضمیر عربی قاعدہ کے رو سے جا سکتی ہے.کہا جا سکتا ہے کہ قُلُوْبٌ کا لفظ پہلے ہے اور حِجَارَۃٌ کا لفظ بعد میں.اور اس سے پہلے کی جو ضمیریں ہیں وہ حِجَارَۃٌ کی طرف پھیری جا چکی ہیں.پس حِجَارَۃٌ کا لفظ جو بعد میں استعمال ہوا ہے اُس کی طرف ضمائر کے پھیرے جانے کے بعد ایک ضمیر کا قلوب کی طرف جو حِجَارَۃٌ سے پہلے بیان ہوا ہے.پھیرنا صحیح نہیں معلوم ہوتا.لیکن یہ اعتراض درست نہ ہو گا کیونکہ عربی زبان میں ضمائر کو اس طرح پھیرنا جائز ہوتا ہے.اﷲتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ١ؕ وَ تُسَبِّحُوْهُ
Page 217
ُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا (الفتح :۱۰) تاکہ تم اﷲ پر ایمان لاؤ اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس ( یعنی رسول ) کی مدد کرو اور اسکی عزّت کرو اور صبح شام اس ( یعنی اﷲ) کی تسبیح کرو.اس آیت میں پہلے ﷲ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور پھر رسول کا.لیکن اس کے بعد پہلے دو ضمیریں رسول کی طرف پھیری گئی ہیں اور پھر تیسری ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف پھیری گئی ہے.یہ مثال بالکل اس آیت کے مضمون کے مطابق ہے آیت زیر تفسیر میں بھی پہلے قُلُوب کا لفظ ہے پھر حِجَارَۃ کا ہے اور یہاں بھی پہلے دو ضمیریں حِجَارَۃ کی طرف جو بعد میں ہے پھیری گئی ہیں اور پھر ایک ضمیر قُلُوب کی طرف جو اس سے پہلے ہے پھیری گئی ہے.اسی طرح ایک اور مقام پر اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.وَ لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّاۤ اَنْ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ١ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ١ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ١ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا١ۚ وَ مَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.(البقرة :۲۳۰)اس آیت میں تَأْخُذُوْا کی ضمیر اور طرف گئی ہے اور خِفْتُمْ کی ضمیر اور طرف.حالانکہ جملہ ایک ہی ہے یعنی تَاْخُذُوْا سے مراد خاوند ہیں اور خِفْتُمْسے مراد دوسرے لوگ ہیں.پس ایک جگہ پر بیان کردہ ضمائر کو مختلف مرجعوں کی طرف پھیرنا عربی کے لحاظ سے بالکل درست ہے اور اسے اصطلاح میں انتشار ضمائر کہتے ہیں اور اسے نحوی جائز قرار دیتے ہیں.(جواہر الحسان للثعالبی) وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ اور اﷲ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو.اس جملہ سے صاف ظاہر ہے کہ ان آیات میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے زمانہ کے تھے.فرماتا ہے تمہارے یہ اعمال اور شرارتیں جو تم رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے خلاف کرتے ہو خدا تعالیٰ کی نظر سے پوشیدہ نہیں.وہ ان کے بدلہ میں تمہیں ضرور سزا دے گا.اَفَتَطْمَعُوْنَ۠ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ (اے مسلمانو)کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَ کلام کو سنتے ہیں پھر اسے سمجھ لینے کے بعد اس (کے مطلب) کو بگاڑ دیتے ہیں اور وہ( اس عمل کے
Page 218
هُمْ يَعْلَمُوْنَ۰۰۷۶ بد نتائج کو خوب )جانتے ہیں.حَلّ لُغَات.تَطْمَعُوْنَ.طَمِعَ سے مضارع جمع مذکّر مخاطب کا صیغہ ہے اور طَمِعَ فِیْہِ ( یَطْمَعُ) کے معنے ہیں حَرِصَ عَلَیْہِ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے دل میں خواہش نے جوش مارا.( اقرب) مفردات میں ہے اَلطَّمْعُ نُزُوْعُ النَّفْسِ اِلَی الشَّیْ ءِ شَھْوَۃً لَہٗ کہ کسی شے کے حصول کے لئے طبیعت کا انتہائی اشتیاق طمع کہلاتا ہے نیز طَمِعَ فِیْہِ وَ بِہٖ کے معنے ہیں حَرِصَ عَلَیْہِ وَرَجَاہُ کسی چیز کے حصول کی خواہش کی اور اس کو حاصل کرنے کی امیدرکھی ( تاج ) اَلطَّمْعُ ضِدُّ الْیَأْسِ کہ طمع کے ایک معنے امید کے بھی ہیں.(لسان) پس اَفَتَطْمَعُوْنَ کے معنے ہوں گے (۱) کیا تم امید رکھتے ہو (۲) کیا تم خواہش رکھتے ہو.اَنْ یُّؤْمِنُوْا لَکُم.یُؤْمِنُوْا اصل میں یُؤْمِنُوْنَ ہے اَنْ پہلے آنے کی وجہ سے ن گِر گیا باقی یُؤْمِنُوْا رہ گیا.یہ اٰمَنَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اٰمَنَ لَہٗ کے معنے ہیں خَضَعَ وَ انْقَادَ کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا اور اس کی بات کو مان لیا اور اٰمَنَ بِہٖ کے معنے ہیں صَدَّقَہٗ اس کو سچا قرار دیا.اور جب اٰمَنَہٗ کہیں تو اس کے معنے ہوں گے اس کو امن بخشا.(اقرب) پس اَفَتَطْمَعُوْنَ۠ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ کے معنے ہوں گے کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے.فَرِیْقٌ.اَلْفَرِیْقُ: اَلطَّائِفَۃُ مِنَ النَّاسِ لوگوں کا گروہ.اَکْثَرُ مِنَ الْفِرْقَۃِ.فِرْقۃٌ کے معنے بھی اَلطَّائِفَۃُ مِنَ النَّا سِ کے ہیں لیکن فریق کا لفظ فِرقہ سے بڑے گروہ پر بھی جو کسی بڑی جماعت کا حصّہ ہو استعمال ہوتا ہے وَرُبَّمَا اُطْلِقَ الْفَرِیْقُ عَلَی الْجَمَاعَۃِ قَلَّتْ اَوْکَثُرَتْ بعض اوقات لفظ فریق سے کسی بڑی جماعت کے حصّہ کی بجائے خود ایک مستقل جماعت بھی مراد لی جاتی ہے خواہ اس کے افراد تھوڑے ہوں یا زیادہ.(اقرب) یُحَرّفُوْنَہٗ.یُحَرِّفُوْنَہٗ حَرَّفَ سے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور حَرَّفَہٗ کے معنی ہیں غَیَّرَہٗ کسی چیز کو اس کی اصلی حالت سے تبدیل کر دیا اور حَرَّفَ الْکَلَامَ کے معنی ہیں غَیَّـرَہٗ عَنْ مَّوَا ضِعِہٖ کسی کلام کے الفاظ کو ان کی جگہوں سے تبدیل کر دیا.( اقرب) امام راغب لکھتے ہیں تَحْرِیْفُ الْکَلَامِ اَنْ تَجْعَلَہٗ عَلٰی حَرْفٍ مِّنَ الْاِحْتِمَـالِ یُمْکِنُ حَمْلُہٗ عَلَی الْوَجْھَیْنِ یعنی کسی کلام میں تحریف کرنے سے یہ مراد ہوتی ہے کہ کلام میں جس رنگ
Page 219
اور جس موقع کی وجہ سے خاص معنے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی بجائے کلام کو ایسے رنگ میں ڈھال دینا کہ اس کے مخصوص معنوں کی بجائے اس میں دو احتمال پیدا ہو جائیں جس کی وجہ سے پڑھنے والے پر اصل معنی ظاہر نہ ہوں.(مفردات) تفسـیر.اٰمَنَ بِہٖ اور اٰمَنَ لَہٗکے معنوں میں فرق اٰمَنَ لَہٗ کے معنے جیسا کہ حَلِّ لُغَات میں لکھا گیا ہے اطاعت اور فرمانبرداری یا جزوی تصدیق کے ہوتے ہیں.گو اس کے معنے کلّی تصدیق کے بھی ہیں لیکن کلّی تصدیق کے لئے زیادہ تر اٰمَنَ کا صلہ باء آتا ہے جیسے سورۂ بقرہ کے پہلے رکوع میں آتا ہے وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ١ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.(البقرۃ:۵) قرآن کریم میں اٰمَنَ یا اٰمَنُوْا کے الفاظ کے ساتھ جہاں صلہ مذکور ہوا ہے وہاں دو ہی صلے آتے ہیں باء کا صلہ اور لام کا صلہ.اِن میں سے باء کا صلہ تریپن دفعہ آیا ہے اور لام کا صلہ آیتِ زیر تفسیر کے علاوہ تین جگہوں میں آیا ہے.لیکن جہاں کہیں بھی لام کا صلہ آیا ہے وہاں اطاعت اور فرمانبرداری کے معنے ہی زیادہ مرجّح ہیں.چنانچہ سورۂ یونس میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَاۤ اٰمَنَ لِمُوْسٰۤى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَاۡىِٕهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ.(یونس :۸۴) یعنی گو دل میں تو بنی اسرائیل کا بہت سا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا مگر ظاہر ہو کر حضرت موسیٰ ؑکے احکام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق صرف کچھ ہی لوگوں کو ملی تھی.کیونکہ باقی لوگ فرعون اور اُس کے معاونوں کی ایذاء سے ڈرتے تھے.اسی طرح سورۂ طٰہٰ میں آتا ہے فرعون نے ساحروں سے کہا اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ (طٰہٰ :۷۲) یہاں بھی یہ معنے ہو سکتے ہیں کہ تم نے موسیٰ کی فرمانبرداری اختیارکر لی اور میری بغاوت کی.کیونکہ فرعون کو قلبی ایمان کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی.اس کوتوموسیٰ علیہ السلام کی سیاسی فرمانبرداری اور اطاعت کی ہی فکر تھی.یہی آیت سورۂ شعراء ع ۳میں بھی آئی ہے.پس قرآن کریم کے محاورہ کے لحاظ سے جہاں ایمان کا ذکر ہو وہاں اٰمَنَ بِہٖ کے الفاظ آتے ہیں اور جہاں اطاعت کا ذکر ہو وہاں اٰمَنَ لَہٗ کے الفاظ آتے ہیں.ایمان سے مضارع مخاطب کا صیغہ بارہ جگہ قرآن کریم میں باء کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور ایک جگہ سورۂ دخان میں لام کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے.جہاں آتا ہے.وَ اِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ (الدّخان :۲۲)یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول فرعونیوں کے متعلق ہے.اِس جگہ بھی اطاعت کے معنے ہی زیادہ مناسب ہیں کیونکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول درج ہے کہ اَنْ اَدُّوْۤا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ (الدخان:۱۹).اﷲ کے بندے میرے سپرد کر دو.پس اِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ کے معنے یہ ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے یعنی خوشی
Page 220
سے بنی اسرائیل کو میرے سپرد نہیں کرتے تو فَاعْتَزِلُوْنِ کم سے کم میرے راستہ میں روکیں تو پیدا نہ کرو.اٰمَنَ کے اسم فاعل کے صیغہ میں مومنین کے ساتھ دو جگہ پر باء کا صلہ استعمال ہوا ہے اور وہاں ایمان کے ہی معنے ہیں.صرف ایک جگہ پر لام کا صلہ استعمال ہوا ہے جہاں اُس کے معنے بات مان لینے کے ہیں.یہ لَام کے صلہ کا استعمال سورۂ یوسف میں ہے جہاں آتا ہے.وَ مَاۤ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ ( یوسف :۱۸) آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں.یہاں بھی اُس ایمان کا ذکر نہیں جس کا خدایا خدا تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے بلکہ جزوی تصدیق کا ذکر ہے.ایمان سے جمع متکلّم کا صیغہ چار جگہ باء کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور آٹھ جگہ لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے.اِن میں سے ایک جگہ سورۂ شعراء میں ہے جہاں کفار کا یہ قول درج ہے کہ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ (الشّعراء:۱۱۲) انہوں نے کہا کیا ہم تیرے فرمانبردار ہو جائیںحالانکہ تیرے فرمانبردار رذیل لوگ ہیں.یہاں بھی ایمان کا لفظ فرمانبرداری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے (۲) پھر سورۂ مومنون میں فرعونیوں کا یہ قول لکھا ہے کہ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَ قَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ (المؤمنون:۴۸) یہاں بھی فرمانبرداری کے ہی معنے ہیں.فرعون کی قوم کہتی ہے کہ کیا ہم ایسے دو آدمیوں کی اطاعت اختیار کر لیں جن کی قوم ہماری غلام ہے گویا ہم غلاموں کے غلام ہو جائیں (۳) تیسرا مقام سورۂ آل عمران آیت ۱۸۴ہے وہاں یہ الفاظ ہیں اَلَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَاۤ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ.وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اﷲ تعالیٰ نے ہمیں تاکید کر دی تھی کہ ہم کسی رسول کی بات نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس وہ قربانی نہ لائے جس کو آگ کھاتی ہو.یہاں دونوں معنے ہو سکتے ہیں.لیکن چونکہ دوسرے مقامات میں جہاں لام استعمال ہوا ہے یا تو فرمانبرداری کے معنے لئے گئے ہیں یا کسی خاص بات کو تسلیم کرنے کے معنے لئے گئے ہیں کلّی ایمان کے معنے نہیں لئے گئے اور چونکہ یہ معنے بھی اِس جگہ پرچسپاں ہو سکتے ہیں اس لئے دوسری آیات کے تابع یہاں بھی یہی معنے سمجھے جائیں گے کہ اس جگہ کلّی ایمان مراد نہیں بلکہ فرمانبرداری مراد ہے (۴) چوتھی جگہ سورۂ توبہ میں ہے وہاں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے.يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ١ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ( التوبۃ :۹۴) منافق تمہارے پاس عذر کرتے ہوئے آتے ہیں جبکہ تم جنگ سے اُن کی طرف واپس آتے ہو.اے رسول تم انہیں کہہ دو کہ عذر مت کرو.ہم تمہاری بات اِس بارہ میں ماننے کے لئے تیار نہیں کیونکہ اﷲ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے.یہاں بھی ایک خاص بات کے ماننے کا ذکر ہے کلّی ایمان کا ذکر نہیں.کیونکہ نبی اپنی جماعت کے افراد پر ایمان نہیں لایا
Page 221
کرتا (۵) پانچواں مقام سورۂ بنی اسرائیل ہے.یہاں دو جگہ نُؤْمِنُ کے ساتھ لام کا صلہ استعمال ہوا ہے.ایک جگہ فرماتا ہے.قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا ( بنی اسراءیل:۹۱) اس جگہ بھی اطاعت اور فرمانبرداری ہی مراد ہے کیونکہ یہاں دنیوی سامانوں اور بادشاہت کا ذکر ہے.دوسرے مقام پرا سی رکوع میں یوں آتا ہے.وَ لَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ( بنی اسراءیل:۹۴) ہم تیرے چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں بھی ایک خاص بات ماننے کا ذکر ہے کلّی ایمان کا ذکر نہیں (۶) اِسی طرح سورۂ بقرہ میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً (البقرۃ :۵۶) یہاں قطعی طورپر فرمانبرداری کے ہی معنے ہیں اس لئے کہ وہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلّی ایمان کا اظہار تو ملکِ مصر سے نکلتے ہوئے بھی کر چکی تھی.پس یہاں فرمانبرداری کے ہی معنے ہیں یا یہ مراد ہے کہ ہم تیری اس خاص بات کو نہیں مانیں گے (۷)ساتویں جگہ سورۂ اعراف میں وہ جگہ لام کا صلہ استعمال ہواہے ایک جگہ آتا ہے وَ قَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا١ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ (الاعراف:۱۳۳) یہ آیت بنی اسرائیل کے مصر سے نکل جانے کے مطالبہ کے بعد آئی ہے پس اس کے معنے بھی یہی ہیں کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے اور بنی اسرائیل کو نہیں بھیجیں گے.چنانچہ اس کے ایک آیت کے بعد ہی دوسری دفعہ لام کا صلہ نُؤْمِنُ کے بعد استعمال ہوا ہے اور وہاں قطعی طور پر بات ماننے کے معنے ہیں کیونکہ وہاں یہ الفاظ ہیں.لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ (اعراف:۱۳۵)ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے.اگر کلّی ایمان مراد ہوتا تو وہ یُوں کہتے کہ بنی اسرائیل کو بھیجنا تو الگ رہا ہم تجھ پر ایمان لا کر خود بھی تیرے ساتھ روانہ ہو جائیں گے.اٰمَنَ سے غائب کے صیغہ کا استعمال مفرد اور جمع دونوں ملا کر قرآن کریم میں ۸۰ دفعہ ہوا ہے.اِن میں سے ۷۷ جگہ باء کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور دو جگہ لام کا صلہ استعمال ہوا ہے.ایک تو اسی آیت زیربحث میں اور دوسرے سورۂ توبہ میں.سورۂ توبہ ع ۸ میں اﷲ تعالیٰ رسول کریم صلے اﷲ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے یُؤْمِنُ بِاللہِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤمَنِیْنَ (التوبۃ :۶۱) یہاں صاف طور پر بات ماننے کا ذکر ہے چنانچہ اﷲ تعالیٰ کے لئے باء کا صلہ استعمال ہوا ہے جس پر ایمان کلّی ہوتا ہے اور مومنوں کے لئے لام کا صلہ استعمال ہوا ہے جس کے معنے بات ماننے کے ہیں اور اس جگہ ذکر بھی یہی ہے کہ منافق کہتے ہیں رسول کریم صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم ہمارے خلاف دوسروں کی باتیں قبول کر لیتے ہیں.اﷲتعالیٰ فرماتا ہے ہمارا رسول ٹھیک کرتا ہے.اس کا طریق یہی ہے کہ وہ اﷲ پر کلّی ایمان لاتا ہے اور مومنوں پر اعتبار کرتا ہے.
Page 222
غرض قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی لَام کا صِلہ استعمال ہوا ہے اُس کے معنے یا تو فرمانبرداری کے اور یا کسی خاص بات کے تسلیم کرنے کے ہوتے ہیں.کلّی ایمان جو خدا اور اُس کے رسولوں پر لایا جاتا ہے اِن معنوں میں لام کا صلہ استعمال نہیں ہوتا.پس اَفَتَطْمَعُوْنَ۠ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ کے معنے یہ ہیں کہ کیا تم امید کرتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیںگے.کُمْ کی ضمیر بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ کلّی ایمان تو خدا اور رسول پر ہوتا ہے مومنوں پر نہیں ہوتا.اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگ یہودیوں پر حُسن ظنی رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ صلح اور محبت اور پیار سے رہیں گے تو وہ سچ کہتے ہیں.اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ایسی امید رکھتے ہو تو سخت غلطی کرتے ہو.معاہدوں کو پورا کرنا شرافت ِ نفس یا خشیت اﷲ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.جو آدمی جھوٹ ،فریب اور دغا سے کام لیتا ہے اُس سے یہ امید کرنا کہ وہ معاہدہ کو پورا کرے گا بالکل خلاف عقل ہے.غرض اﷲ تعالیٰ اِس آیت میں مومنوں کو توجہ دلاتا ہے کہ تم اِن یہودیوں کے حالات کو دیکھو کہ کس طرح جھوٹ اور فریب سے کام لے رہے ہیں اُن کا جھوٹ اور فریب سے کام لینا اِس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا.چنانچہ فرماتا ہے.وَ قَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ اُن میں سے ایک گروہ بظاہر يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ پر عامل ہے یعنی اﷲ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے مگر ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ پھر وہ گروہ اُس کو اپنے مقام سے پھرا دیتا ہے مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ بعد اِس کے کہ وہ اُس کو خوب اچھی طرح سمجھ چکا ہوتا ہے وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.اور اس حالت میں تحریف کا مرتکب ہوتا ہے کہ اُسے اپنے اس گناہ کا پورا علم ہوتا ہے.یعنی تحریف گو بُری بات ہے لیکن اس صورت میں کہ انسان سے اُس کلام کے متعلق تحریف ہو جائے جس کو وہ سمجھا نہیں یا سمجھ توگیا ہو مگر بات بیان کرتے ہوئے غلطی سے کچھ اور مُنہ سے نکل جائے تحریف ، تحریف کرنے والے کی شرارت پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اُس کی ناسمجھی یا غلطی پر دلالت کرتی ہے مگر اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِن یہودیوں کے حق میں یہ دونوں عذر موجود نہیں.وہ اﷲ تعالیٰ کے کلام کے اصل مفہوم کو سمجھ کر پھر اُس کے خلاف بیان کرتے ہیں اور پھر یہ خلاف اِس وجہ سے نہیں ہوتا کہ نادانستہ اُن کے مُنہ سے کوئی بات غلط نکل جاتی ہے بلکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اُس کا اُنہیں علم ہوتا ہے.پس جو لوگ اتنا بڑا افتراء کر سکتے ہیں اور اتنا بڑا ظلم کسی دوسری قوم کے مذہب اور دیانت کے متعلق کر سکتے ہیں یا خود اپنے مذہب یا اپنی قوم کے متعلق کر سکتے ہیں اُن کے متعلق یہ کب اُمید کی جا سکتی ہے کہ وہ شرافت اور دیانت کے ساتھ اپنے معاہدوں کو نباہیں گے.اگر تو کلام اﷲ سے اِس جگہ پر یہودیوں کی کتابیں مراد لی جائیں جیسا کہ بالعموم پرانے مفسروں نے مراد لی ہے تو پھر بھی یہ بات عقل کے خلاف ہے.کیونکہ جو شخص اپنے مذہب سے غدّاری کرتا ہے وہ دوسری قوم سے کس
Page 223
طرح دیانت داری کا معاملہ کرے گا.اور اگر کلام اﷲ سے قرآن کریم مراد لیا جائے جیسا کہ بعض سابق مفسّروں نے بھی یہ معنے کئے ہیں اور میرے نزدیک یہی معنے سیاق و سباق سے نکلتے ہیں تو پھر بھی وہ یہودی جن کا اس جگہ ذکر ہے قابلِ اعتبار نہیں رہتے کیونکہ کلام الٰہی کسی قوم کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اور اس کے متعلق اُس کے جذبات سب سے زیادہ نازک ہوتے ہیں اگر یہودی قرآن کریم کو بگاڑ کر اور اسکے غلط معنے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے عادی تھے اور مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کا اس بارہ میں کوئی خیال نہیں رکھتے تھے تو اُن سے یہ کیونکر امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اُن سے کئے ہوئے دنیوی معاہدات کو پورا کریں گے.جو شخص کسی کے نازک ترین جذبات کو مجروح کر دیتا ہے اُس سے یہ کب امید کی جا سکتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پروا کرے گا.اِس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ قران کریم کی آیتوں کو اُن کے سیاق و سباق سے جُدا کر کے اور غلط معنے کر کے لوگوں میں اسلام کے خلاف جوش پھیلایا کرتے تھے اور یہ عادت ہمیشہ سے انبیاء کے دشمنوں میں چلی آئی ہے.کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خلاف یہ حربہ دشمن نے نہیں چلایا.بلکہ کوئی سچائی دنیا میں ایسی نہیں ہوئی جس کے خلاف اُس کے دشمنوں نے یہ حربہ نہ چلایا ہو.سچائی کی دشمنی جھوٹ پر انسان کو مجبور کر دیتی ہے.آخر سچی بات کی مخالفت کوئی شخص کر ہی کس طرح سکتا ہے اور اُس کے خلاف لوگوں کو بھڑکا ہی کس طرح سکتا ہے.اِسی صورت میں سچائی کی مخالفت انسان کر سکتا ہے جبکہ سچ کو جھوٹ کا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرے.آج اِس زمانہ میں بھی سب سے بڑا گناہ دنیا میں یہی ہو رہا ہے اور یہی چیز صداقت کے قبول کرنے سے لوگوں کو محروم کر رہی ہے.اگر اس زمانہ کے لوگ اِس بات کا تہیّہ کر لیں کہ اپنے مخالف کے مذہب کو غلط رنگ نہیں دیں گے اور جو کچھ وہ کہتا ہے اُس کو اصل شکل میں اپنے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو سچائی کا دریافت کرنا ہرگز مشکل نہ رہے اور تفرقہ اور شقاق اور نفاق بہت جلد دنیا سے دُور ہو جائے.وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اٰمَنَّا١ۖۚ وَ اِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب ایک دوسرے سے علیحدگی میں ملتے اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْۤا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ہیں تو ( ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے ) کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ بات جو اللہ نے تم پر کھولی ہے اس لئے بتا تے ہو
Page 224
لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ١ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۰۰۷۷ کہ وہ اس کے ذریعہ سے تمہارے رب کے حضور میں تم سے بحث کریں.کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے.تفسیر.پہلی آیت میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہودی لوگ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنے میں ایسا تعصّب برتتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطالب کو دیدہ و دانستہ بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو برانگیختہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں.اب آیت زیر تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جو اُن کا تمسخر کا طریق ہے اس کے علاوہ خود مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا سلوک غیر مخلصانہ ہے وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اُن کے سامنے یوں اظہار کرتے ہیں کہ گویا وہ دل سے اسلام کی سچائی کے قائل ہیں بلکہ اُن کے سامنے وہ ایسے دلائل بھی بیان کرتے ہیں جنہوں نے اُن کو اسلام کی سچائی کا قائل کر دیا اور اپنی کتابوں کی ایسی پیشگوئیاں بیان کرتے ہیں جو ان کے نزدیک رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم پرچسپاں ہوتی اور آپ کی سچائی کو ظاہر کرتی ہیں.لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو ایک دوسرے پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو جن سے اُنہیں تمہارے مذہب کے خلاف حجت قائم کرنے میں مدد ملتی ہے.اُن کی اِس کارروائی سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت محض مذہبی مخالفت ہی نہیں بلکہ سیاسی اور تمدّنی طور پر بھی وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں کیونکہ وہ صرف مذہب پر ہی اعتراض نہیں کرتے بلکہ اُن کی مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں بھی سنجیدہ نہیں اور اُن میں بھی فریب اور پُرکاری کے جذبات کار فرماہیں.یہودیوں کے اخلاق کا جو پہلو اِس آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی نہایت ہی خطرناک ہے.یہودی لوگ مسلمانوں سے ملتے.اُن سے دوستیوں کا اظہار کرتے اور کہتے کہ ہم بھی دل سے اسلام کی صداقت کے قائل ہیں.لیکن جب اُن سے علیحدہ ہوتے تو آپس میں ایک دوسرے کو زجر کرتے کہ تم نے کیوں اُن باتوں کو جو اﷲتعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں مسلمانوں پر ظاہر کیا.اِس کا نتیجہ تو یہ ہو گا کہ وہ اِن باتوں کو تمہارے خلاف استعمال کریںگے.گویا وہ یہ تو تسلیم کرتے تھے کہ جن باتوں کا اُنہوں نے مسلمانوں سے ذکر کیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہیں اور اس امر کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ باتیں اسلام کی تائید میں ہیں.لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اُن باتوں کا مسلمانوں کو علم ہو تا ایسا نہ ہو کہ وہ اُنہیں یہودیت کے خلاف استعمال کریں.گویا اُن کے نزدیک خدا تعالیٰ کی بات بیشک جھوٹی نکلے ،
Page 225
خدا تعالیٰ کا منشاء بے شک پورا نہ ہو لیکن پبلک کی نظر میں یہودیوں کی عزت قائم رہے.جس قوم کے اخلاق کی یہ حالت ہو جائے وہ دینی طور پر کس مصرف کی ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس سے دین اور اخلاق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا.اور جہاں تک مذہب اور اخلاق کا تعلق ہے اس قوم کی تباہی میں ہی دین اور دنیا کی بہتری ہے.پس یہ اخلاقی حالت جو رسول کریم صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کے ظہور کے بعد یہودیوں نے پیش کی اس بات کا ایک زبردست ثبوت تھا کہ اب یہ قوم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی مستحق نہ رہی تھی اور خدا تعالیٰ کا نبی اب اِس قوم سے باہر ہی آنا چاہیے تھا.اِس آیت کے آخر میں اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.یعنی کیا یہ اِن باتوں سے رُکتے نہیں.اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ بات کیا کرتا ہے جو اُس کے لئے یا اُس کی قوم کے لئے عزّت کا موجب ہو.مگر یہ بات جو اُوپر بیان کی گئی ہے اس کا کہنے والا تو صاف لفظوں میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا غدّار ہے.وہ خدا تعالیٰ کے منشاء کو سمجھتا ہے، اُس کی پیشگوئیوں کو سمجھتا ہے.مگر صاف لفظوں میں اقرار کرتاہے کہ میں خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کی سچائی ظاہر نہیں ہونے دوں گا اور خدا تعالیٰ کے منشاء میں روک بنوں گا.جو شخص اتنا خطرناک دعویٰ اپنے دوستوں کے سامنے کرتا ہے اس کے بے عقل ہونے میں کیا شبہ ہے.اُس کی مثال تو وہی ہے کہ ع چہ دلاور است دُزدے کہ بکف چراغ دارد اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اس کے معنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خدا نے جو تم پر کھول دیا یعنی عقلی طور پر یا معجزوں کے ذریعہ سے اسلام کی سچائی کو ظاہر کر دیا.اور مطلب یہ ہے کہ خواہ تم پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی ہو پھر بھی تم کو یہ بات مسلمانوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے.دوسرے معنے فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ پیشگوئیاں جو رسول کریم صلے اﷲ علیہ وسلم کے متعلق بائبل میں بیان ہو چکی ہیں اور جو رسول کریم صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی ذات میں پوری ہو کر آپ کی صداقت کو ثابت کر رہی ہیں اُن کو کیوں مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے ہو.یہ دونوں معنے ایک ہی وقت میں اِس آیت میں پائے جاتے ہیں.دونوں قسم کے لوگ یہودیوں میں تھے کچھ وہ جو بائبل کے پوری طرح واقف نہیں تھے لیکن وہ عقلی دلائل سے اور اُن معجزات کے ذریعہ سے جو آنحضرت صلی اﷲ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے رسول کریم صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی صداقت کے دل میں قائل ہو چکے تھے.اور کچھ وہ لوگ جو بائبل کے ماہر تھے اُن پر اُن پیشگوئیوں کی وجہ سے جو بائبل میں پائی جاتی ہیں اور آپ کی ذات میں پوری ہوئیں آپ کی صداقت کھل گئی تھی.وہ مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کے موقع پر اُن پیشگوئیوں کا ذکر کر دیتے
Page 226
تھے اور کہتے تھے کہ ہماری کتب کی فلاں فلاں پیشگوئیوں کے مطابق بھی محمد رسول اﷲ صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم سچے ثابت ہوتے ہیں.عِنْدَ رَبِّكُمْ کے الفاظ جو اس آیت میں پائے جاتے ہیں اُن کے متعلق کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے.عام معنے اِس جملہ کے یہ بنتے ہیں کہ بعض یہودی اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کے پاس وہ پیشگوئیاں بیان کرتے ہو جو تمہاری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں یا یہ کہ اُن کے سامنے اقرار کرتے ہو کہ عقلی طور پر تو محمد رسول اﷲ صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی سچائی ثابت ہوتی ہے مگر کیوں اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اس کی وجہ سے وہ تمہارے رب کے سامنے تم سے بحث کریں گے اور تم کو مجرم قرار دیں گے.اِن معنوں پر اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ اﷲ تعالیٰ توعالم الغیب ہے مسلمانوں کے نزدیک بھی اور یہودیوں کے نزدیک بھی.پھر یہ کیونکرخیال کیا جا سکتا ہے کہ یہودی اپنے ساتھیوں پر اس لئے ناراض ہوتے تھے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے دلی یقین یا بائبل کی پیشگوئیوں کا اظہار کیوں کر دیتے ہیں اِس کی وجہ سے مسلمان قیامت کے دن اُن کے خلاف حجت قائم کر سکیں گے.یہ اعتراض اِسی صورت میں پڑ سکتا ہے جبکہ یہ تسلیم کیا جائے کہ تمام کے تمام انسانوں کا ایمان خدا تعالیٰ پر ایک قسم کا ہے مگر یہ بات درست نہیں.دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے سوا بندوں کو بھی عالم الغیب قرار دیتے ہیں اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کو بھی پوری طرح عالم الغیب قرار نہیں دیتے.چنانچہ قرآن کریم میں کفار کی اس گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے جو قیامت کے دن اُن میں اور خدا تعالیٰ میں ہو گی فرماتا ہے ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا وَ اللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (الانعام :۲۴)یعنی جب کفار پر پوری طرح حجت تمام ہو جائے گی تو اُس وقت وہ ایک ہی جواب کی رٹ لگائے جائیں گے اور ڈھیٹھ بن کر یہی کہتے چلے جائیں گے کہ ہمیں قسم ہے اﷲ اپنے رب کی کہ ہم مشرک نہیں تھے.عالم الغیب ہستی کے سامنے اِس قسم کا جواب جاہلانہ ہے.مگر دنیا میں یہ جاہلانہ خیالات پائے جاتے ہیں.ایسے فلسفی موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر اُس کے علم کو حاوی نہیں سمجھتے.اس کی طرف کلّی علم کو تو منسوب کرتے ہیں مگر اس بات کے منکر ہیں کہ اُسے تمام جزئیات کا بھی علم ہے.ایسے لوگوں سے یہ امر بعید نہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہوں کہ کیوں تم نے اپنے دلی خیالات کو مسلمانوں پر ظاہر کیا.یہ قیامت کے دن اِس گواہی کو تمہارے خلاف پیش کریں گے.اِس قسم کی جہالت یہودی اَور باتوں میں
Page 227
بھی کرتے رہے ہیں.مثلاًاِ سی سورۃ میں آگے چل کر آئے گا کہ یہودی لوگ کہتے تھے ابراہیم ؑ یہودی تھا حالانکہ یہودیت موسیٰ ؑ سے چلی بلکہ موسیٰ ؑ سے بھی نہیں.یہودیت کا نام داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو حاصل ہوا مگر باوجود اس کے وہ کہہ دیتے تھے کہ ابراہیم ؑیہودی تھا.جب قوموں میں تنزّل پیدا ہوتا ہے تو لوگ اِس قسم کی متضاد اور مخالف باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ درحقیقت اُن کے ایمان کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہوتی بلکہ سنی سنائی باتوں پر ہوتی ہے اور سنی سُنائی باتیں اوّل تو متضاد خیالات کے لوگوں سے پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اِس لئے خود اُن میں تضاد پایا جاتا ہے.دوسرے جب کوئی شخص عقل کے خلاف بات پر عقیدہ رکھے گا تو اُسے سچا ثابت کرنے کے لئے اِسے عقل کے خلاف باتیں کرنی پڑیں گی.سچّے دین کو جو آخر میں کامیابی ہوتی ہے اُس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اِس کے اندر تضاد نہیں ہوتا.جب کبھی کسی اِنسان پر تعصب سے خالی ہونے کی گھڑی آتی ہے وہ سچائی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح الہٰی جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے.دوسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ عِنْدَ کے معنے عربی زبان میں کئی ہیں.جن میں سے ایک معنے ’’پاس‘‘ کے ہیں اور دوسرے معنے ’’ مطابق حکم‘‘ کے.چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں ھٰذا عِنْدَ فُـلَانٍ حَرَامٌ.یعنی یہ چیز فلاں شخص کے حکم کے مطابق حرام ہے.اور قرآن کریم میں بھی محاورہ استعمال ہوا ہے.چنانچہ سورۂ نور میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو چار گواہ ساتھ لائے.فرماتا ہے فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰٓىِٕكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ( النور:۱۴ ) یعنی الزام لگا نے والے اگر چار گواہ نہ لا سکیں تو وہ اﷲ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹے ہیں.یہاں عِنْدَ کے معنے پاس نہیں ہو سکتے کیونکہ بالکل ممکن ہے ایک شخص کسی پر الزام لگائے اور وہ الزام لگانے میں سچا بھی ہو لیکن وہ چار گواہ نہ لا سکے پس گو وہ خدا تعالیٰ کے علم میں سچا ہو گا مگر خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جھوٹا قرار دیا جائے گا اور اُس کی بات پر اعتبار نہیں کیا جائے گا تاکہ جھوٹے لوگوں کو یہ جرأت پیدا نہ ہو کہ وہ کسی شخص پر بلا ثبوت دشمنی کی وجہ سے جھوٹا الزام لگاویں.لیکن باوجود اِس کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کے علم میں بھی جھوٹا ہے کیونکہ اﷲ تعالیٰ تو بغیر شہادت کے بھی جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا.پس اس جگہ پر عِنْدَ اللہ کے معنے ’’ مطابقِ حکم‘‘ کے سوا اور کوئی نہیں کئے جا سکتے.بعض علماء نے عِنْدَ کے معنے ’’فِیْ ‘‘ کے بھی کئے ہیں اور مراد یہ لی ہے کہ تمہارے رب کے متعلق جب بحث ہو کیونکہ فِیْ کے معنے ’’ بارہ میں ‘‘ بھی ہوتے ہیں (دیکھو بحر محیط زیر آیت محولہ بالا) بعض لوگوں نے اِس جگہ پر مضاف حذف تصوّر کیا ہے جو عربی قواعد کے لحاظ سے جائز ہے وہ کہتے ہیںعِنْدَ رَبِّكُمْسے مراد ہے عِنْدَ ذِکْرِ رَبِّکُمْ.اور
Page 228
جملے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو تم سے جب کبھی تمہارے رب کے متعلق گفتگو ہو تو وہ تمہاری بتائی ہوئی باتوں کے ذریعہ سے تم سے بحث کریں یعنی جب یہ سوال پیدا ہو کہ آیا محمد رسول اﷲ صلی اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم کی سچائی پر خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی دلیل ہے تو مسلمان لوگ بائبل کی اِن پیشگوئیوں کو نہ پیش کر دیں جو انہوں نے تم سے سُنی ہوں گی.اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.اِس آیت سے ظاہر ہے کہ اسلام نفاق کو اور اخلاص کے بغیر کسی مذہب کے قبول کرنے کو پسند نہیں کرتا.یہی وجہ ہے کہ وہ یہود کے اِس فعل کو کہ وہ پور ایمان حاصل کئے بغیر مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتے تھے بُرا قرار دیتا ہے.اگر اسلام کے نزدیک صرف زبانی اقرار ایمان کے لئے کافی ہوتا تو چاہیے تھا کہ یہود کی اِن حرکات کی تعریف کی جاتی اور اُن کے لئے ایسے مواقع بہم پہنچائے جاتے کہ وہ مسلمانوں سے اور بھی زیادہ ملیں اور اُن کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کریں.اس آیت میں اُن لوگوں کا بھی جواب ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول کریم صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے یہودیوں سے سُن سُنا کر بائبل کے واقعات قرآن کریم میں لکھ دیئے ہیں.ظاہر ہے کہ اِس قسم کا کام کرنے والا شخص اُس ذریعے کو جس سے وہ فائدہ اُٹھاتا ہے بڑھانے کی کوشش کیا کرتا ہے نہ کہ کم کرنے کی.اگر نَعُوْذُ بِاللہ مِنْ ذَالِکَ رسول کریم صلے اﷲ علیہ وآلہٖ وسلم یہودیوں سے سُن کر قرآن کریم میں واقعات لکھ لیا کرتے تھے تو آپؐ یہود کے اس فعل کا بھانڈا کیوں پھوڑتے تب تو چاہیے تھا کہ آپ اُن کا بھانڈا پھوڑنے کی بجائے اُن کے لئے ملاقاتوں کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرتے.اَوَ لَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَ مَا يُعْلِنُوْنَ۰۰۷۸ کیا یہ (اس بات کو) نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے.تفسیر.اِس آیت میں بھی اِس اعتراض کا جواب موجود ہے جو عیسائی مصنّفین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم یہودیوں سے سُن کر بائبل کے واقعات قرآن کریم میں نقل کر دیا کرتے تھے.کیونکہ اس آیت میں اس قسم کے خیالات کی تردید کی گئی ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ضروری خبر اپنے رسول کو خود بتا دیتا ہے.اور کہا گیا ہے کہ کیا یہودی یہ نہیں سمجھتے کہ اﷲ اسے بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور
Page 229
اُسے بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں.یعنی قرآن کریم میں ایسی اخبار بھی موجود ہیں جو اِن یہودیوں نے بیان نہیں کیں اور وہ بھی ہیں جو اُنہوں نے بیان کیںاس سے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان کی ہیں اگر وہ بیان نہ کرتے تب بھی اِس سے قرآن کریم کے مضامین میں کمی نہیں آ سکتی تھی.مخالفینِ صداقت ہمیشہ سے ماموروں پر یہ اعتراض کرتے چلے آئے ہیں کہ وہ زمانہ کی رَو کی پیداوار ہیں.اس زمانہ میں جو خیالات زور پر ہوتے ہیں اُن سے متأثر ہو کر وہ اپنے لئے ایک مقام تجویز کر لیتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب کبھی خدا تعالیٰ کسی مامور کو مبعوث کرنے لگتا ہے اُس کے آنے سے پہلے لوگوں کی توجہ ایک آنے والے مامور کی طرف پھیر دی جاتی ہے.بعض سابق پیشگوئیوں کے متعلق لوگ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ اس زمانہ میں پوری ہوں گی.اور بعض علامات سے وہ یہ استدلال کرنے لگ جاتے ہیں کہ اِسی زمانہ میں وہ موعود مامور آئے گا اور ایسا ہونا ہی چاہیے کیونکہ بعثتِ مامور کے وقت اُس کے ماننے کے لئے دنیا میں سامان پیدا کرنا ایک ضروری امر ہے جسے خدا تعالیٰ نظر انداز نہیں کر سکتا.پس جب وہ مامور آتا ہے تو وہ اُن پیشگوئیوں سے بھی فائدہ اُٹھاتا ہے جن کی طرف اُس کی آمد سے پہلے علماء زمانہ کی نگاہیں اُٹھ چکی ہوتی ہیں.اس سے یہ استدلال کر لینا کہ مامورین زمانہ کی پیداوار ہیں ایک نہایت ہی بودا اعتراض ہے.کیا اِن معترضین کا یہ خیال ہے کہ اﷲ تعالیٰ کو نبی پہلے بھیجنا چاہیے اور اُس کی شناخت کے سامان بعد میں پیدا کرنے چاہئیں؟ اگر خدا تعالیٰ ایسا کرے تو اِس کے معنے تو یہ ہوں گے کہ وہ خود دنیا کو ہدایت سے محروم کرنا چاہتا ہے.یا پھر کیا ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ نبیوں کی شناخت کے سامان تو پہلے سے مہیّا کر دیئے جائیں اور پہلے نبیوں کی بعض پیشگوئیوں کے پورا ہونے کے آثار بھی ظاہر کر دیئے جائیں لیکن وہ نبی اُن پیشگوئیوں سے فائدہ نہ اُٹھائے ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ دوسروں کے خیالات سے متاثر ہے.ادنیٰ غور سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ خیال بھی بالکل باطل ہے.جس چیز کو خدا تعالیٰ نے سچائی کے ظاہر کرنے کے لئے بطور دلیل مہیا کیا ہے اِس سے فائدہ نہ اُٹھانا تو خدا اور اُس کے دین سے غدّاری ہے اور نبی غدّار نہیں ہوتا.پس اس قسم کے اعتراضات خواہ وہ پہلے نبیوں پر ہوئے ہوں یا محمد رسول اﷲ صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم پر ہوئے ہوں یا آپ کے بعد کسی کے متعلق ہوں بالکل لغو ہیں.اﷲتعالیٰ نے آیت زیر تفسیر میں نہایت عمدگی سے اس کو ردّ کر دیا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ باتیں بھی ہماری کتاب میں موجود ہیں جن کو تم بیان کرتے ہو اور وہ باتیں بھی موجود ہیں جن کو تم بیان نہیں کرتے یا بیان نہیں کر سکتے.خدا تو ساری ہی باتوں کا واقف ہے اُس کی طرف سے آنے والی کتاب کسی کے بتائے ہوئے علم کی محتاج نہیں.مگر وہ یہ بھی تو نہیں کر سکتی کہ چونکہ کسی اَور نے
Page 230
ایک علم کا اظہار کر دیا ہے اس لئے خدا کی کتاب میں سے اِس علم کو خارج کر دینا چاہیے.اس سے تو سچائی کا خون ہو گا اور خدا کی کتاب ایسی حرکات سے بالا ہوتی ہے.وَ مِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِيَّ وَ اِنْ هُمْ اور ان میں سے بعض اَن پڑھ ہیں جو چند جھوٹی باتوں کے سوا اپنی کتاب کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے اور وہ صرف اِلَّا يَظُنُّوْنَ۰۰۷۹فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ تُک بندیاں کرتے رہتے ہیں.پس جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں (اور) پھر اس کے ذریعہ سے (کچھ) بِاَيْدِيْهِمْ١ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ تھوڑی (سی) قیمت حاصل کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ یہ (کتاب ) اللہ کی طرف سے ہے ان کے لئے ثَمَنًا قَلِيْلًا١ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ (ایک سخت)عذاب( مقدر )ہے.پھر( ہم کہتے ہیں کہ) ان کے لئے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کے سبب لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ۰۰۸۰ سے (ا یک سخت) عذاب(مقدر ) ہے اور اس کے سبب سے (بھی )عذاب (مقدر )ہے جو وہ کماتے ہیں.تفسیر.اَمَانِیَّ اُمْنِیَّۃٌ کی جمع ہے اور اِس کے معنے ہیں (۱) جس چیز کی تمنّا کی جائے (۲) جھوٹ (۳) جو چیز پڑھی جائے (۴) مقصود.پس آیت کے معنے یہ ہوئے کہ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں صحف ِ بنی اسرائیل کا صرف اتنا علم حاصل ہے کہ وہ اُنہیں پڑھ سکتے ہیں.مراد یہ کہ وہ اچھی طرح اُن کے سمجھنے پر قادر نہیں.گویا اُمّی کے معنے اس جگہ پرمحدود کر لئے گئے ہیں اور ایسے اَنْ پڑھ کے معنے نہیں لئے گئے جو کہ کتاب کو لفظًا بھی نہ پڑھ سکتا ہو بلکہ اِس لفظ سے ایسے اَنْ پڑھ مراد لئے گئے ہیں جو لُغت کی باریکیوں سے واقف نہیں اور صرف موٹے موٹے معنے جانتے ہیں.اِن معنوں کے رُو سے یہود پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنی کتب کے گہرے مطالعہ کی کوشش نہیں کرتے.ذومعانی الفاظ جو اُن میں استعمال کئے گئے ہیں اُن میں سے ایسے معنوں کو تو
Page 231
لے لیتے ہیں جو خدا کی سُنّت اور اُس کے منشاء کے خلاف ہوتے ہیں اور اُن کو چھوڑ دیتے ہیں جو خدا کی سُنّت اور اُس کے منشاء کے مطابق ہوتے ہیں.مسلمانوں کے لئے یہ مضمون بہت ہی عبرت کا موجب ہے.آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے.اکثر مسلمان تو قرآن کریم کے معنے جانتے ہی نہیں اور جو جانتے ہیں وہ صرف محدود علم رکھتے ہیں.قرآنی الفاظ کے اندر جو متعدد مضامین پائے جاتے ہیں اُن کی طرف نہ توجہ کرتے ہیں نہ توجہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ جو توجہ کرے اُسے متأوّل اور کافر قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن کے خزانے بند ہو گئے.اُس کا چلتا ہوا پانی اِن لوگوں کے لئے کھڑا ہو کر بدبودار ہو گیا.مسلمانوں نے اتنا نہ سوچا کہ جس بات کو قرآن کریم نے یہودیوں کے لئے عیب کے طور پر پیش کیا ہے وہ مسلمانوں کے لئے حُسن کیونکر ہو گیا.ایک معنے اُمْنِیَّۃٌ کے تمنّاکے کئے گئے ہیں اِن معنوں کے رُو سے اُمِّیْ کے وہی عام معنے لئے جائیں گے جو عام عربی زبان میں رائج ہیں یعنی بالکل اَنْ پڑھ جو نہ لکھ سکے اور نہ پڑھ سکے.اور آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ یہودیوں میں سے بعض اَنْ پڑھ ہیں جو اپنی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے یا لفظًا تو تلاوت کر سکتے ہیں لیکن اُس کے معنے نہیں جانتے.اُن کا علم کتاب کے متعلق صرف چند آرزؤوں تک محدود ہے یعنی وہ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ ہم نے صحف ِ بنی اسرائیل کو اگر بغیر معنے جاننے کے ہی پڑھ لیا یا لوگوں سے سُن لیا تو بس یہ ہماری نجات کے لئے کافی ہے.گویا خدا کی کتاب اُن کے دل میں صرف ایک تمنّا پیدا کرتی ہے کوئی علم اور نور نہیں بخشتی.یہ حالت بھی آج مسلمانوں میں پیدا ہے اور وہ اس سے ہوشیار نہیں ہوتے.ہوشیار ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے.کروڑوں مسلمان ہیں جو قرآن کریم کی لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور کروڑوں ہیں جو اُس کے لفظ تو پڑھ سکتے ہیں مگر اُن کے معنے نہیں جانتے اور اِن دونوں گروہوں کے دلوں میں قرآن کریم کے پڑھنے اور اُس کے معانی کے جاننے کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی بغیر معنے جاننے کے جب وہ قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں یا یہ بھی نہیں کر سکتے اور کبھی کبھار کسی سے قرآن کریم کی کچھ تلاوت سُن لیتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ان کو نجات حاصل ہو گئی.کیونکہ اُنہوں نے قرآن کریم سُن لیا ہے یا پڑھ لیا ہے حالانکہ نہ اُنہوں نے قرآن پڑھانہ سُنا بلکہ آوازوں کے بعض اُتار چڑھاؤ سنے یا سیاہی کی بعض لکیروں کو دیکھا قرآن کریم تو اُس مضمون کا نام ہے جس پر اُس کے حروف و الفاظ دلالت کرتے ہیں.اگر کسی شخص نے اس مضمون کو نہ پڑھا اور یہ جانتے ہوئے نہ پڑھا کہ قرآن کریم کے اِن الفاظ کا یہی مفہوم ہے اُس نے قرآن کریم ہرگز نہیں پڑھا.اور جس نے اُس کتاب کو ہی نہ جانا جو خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے بھجوائی تھی وہ کیونکر یہ
Page 232
دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ سچے مذہب پر ایمان لایا ہے.میں یہ نہیں کہتا کہ جس کو قرآن کے معنے نہ آئیں اُس کو قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں چاہیے ایسی تلاوت کم سے کم اُسے اُس کے مدّعا کی یاد تو دلاتی رہتی ہے.لیکن اُس کے دل میں معنوں کے جاننے کی خواہش تو ہونی چاہیے اوراُن کے سیکھنے کے لئے اُسے کچھ کوشش تو کرنی چاہیے اگر یہ خواہش موجود ہو اگر اس قسم کی کوشش جاری ہو تو بے شک خدا اور اُس کے رسول کے سامنے ایسا آدمی بری قرار دیا جائے گا.لیکن جب کوشش مفقود ہو اور خواہش کا وجود ہی نہ ہو تو ایساآدمی صرف اپنی تمنّاؤں سے خدا تعالیٰ کو کس طرح خوش کر سکتا ہے.ایک معنے اُمْنِیَّۃٌ کے جو اَمَانِیُّ کا مفرد ہے جھوٹ کے ہیں اور اِن معنوں کے رُو سے آیت کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ یہود میں سے کچھ لوگ اَنْ پڑھ ہیں جو کتاب کے متعلق کچھ علم نہیں رکھتے سوائے کچھ جھوٹوں کے.اِس سے مراد یہ ہے کہ قوم کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کلامِ الہٰی کے معنے تو نہیں جانتے لیکن اُنہیں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ اُنہیں کلامِ الہٰی کے معنے آتے ہیں.گویا علم نہ رکھتے ہوئے عالم کہلانے کا شوق اُن میں ہوتا ہے.اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِس قسم کے یہود بھلا کیا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں یا دوسروںکو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا اِس بات کے کب حقدار ہو سکتے ہیں کہ خدا کا فضل اُن پر نازل ہوتا رہے.وہ تو دین کے دشمن ہیں کہ اپنی جہالت کو خدا تعالیٰ کے سر منڈھ کر اُس کی ہتک کرتے ہیں اور پھر اس جہالت کو لوگوں میں پھیلا کر بھولے بھالے سادہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں.افسوس آج مسلمانوں میں بھی اس قسم کی جماعت کثرت سے موجود ہے.ایسے لوگ اِن میں بھی موجود ہیں جو قرآن کریم کو لفظًا بھی نہیں پڑھ سکتے.مگر وہ اِدھر اُدھر سے سُنے ہوئے قصّوں کو خدا اور اُس کے رسول کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر اصرار کرتے ہیں کہ اُن قصّوں پر یقین کیا جائے اور اُن پر ایمان لایا جائے اور اُن کے احکام پر عمل کیا جائے.اور ایسے بھی ہیں جو عربی زبان کا معمولی سا علم رکھتے ہیں لیکن اُن میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کی باریکیوں کو سمجھ سکیں اور وہ قرآنِ کریم کے متعلق اپنے ناقص علم کے ذریعہ آپ بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں.اور ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کی لفظی تلاوت کر سکتے ہیں مگر اُن لوگوں پر جو لفظی تلاوت بھی نہیں کر سکتے یہ رُعب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے علوم کے ماہر ہیں یہی لو گ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں.اگر قرآن کریم کے پڑھنے اور جاننے کی کوشش کی جاتی اور اُس کے مطالب پر صحیح غور کیا جاتا اور جھوٹوں اور آرزؤوں کی پیروی نہ کی جاتی تو اسلام کو وہ دن دیکھنا نہ پڑتا جو آج ہر مخلص مسلمان کے دل کو غمگین کر رہا ہے.
Page 233
وَ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ.یعنی وہ تمام اقسام کے آدمی جن کا اُوپر ذکر کیا گیا ہے صرف ظن سے کام لیتے ہیں علم اُن کے ساتھ نہیں.وہ بھی جن کو زبان کا پورا علم نہیں صرف گمان سے کام لیتے ہیں اور وہ بھی جو کہ زبان کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے مگر لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو خدا کا کلام قرار دے کر اپنے دماغ کو بھی اُن سے بھر لیتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں میں بھی اُن کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف گمان سے کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس نے اُن کو بات بتائی ہے وہ ضرور سچا ہو گا.فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ اِس آیت میں ایک عجیب اختصار سے کام لیا گیا ہے یعنی بظاہر عبارت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی آیت کا تتمّہ ہے اور اِس میں اُنہی لوگوں کا ذکر ہے جن کا پہلی آیت میں ذکر ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے.مگر عبارت ایسے رنگ میں رکھی گئی ہے کہ پہلی آیت کا تتمّہ معلوم ہوتی ہے.پہلی آیت میں تو اُن لوگوں کا ذکر تھا جو عبرانی زبان سے پوری طرح واقف نہیں تھے اور بائبل کے باریک مضامین کے جانے بغیر اپنے آپ کو دھوکا دیتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کرتے تھے یا اُن کا ذکر تھا جو صرف اِس خواہش اور آرزو میں مگن ہو رہے تھے کہ ہم نے صُحفِ بنی اسرائیل کے الفاظ پڑھ یا سُن لئے ہیں.پس ہماری نجات کے لئے یہ امر کافی ہے.یا اُن لوگوں کا ذکر تھا جو صُحفِ بنی اسرائیل کو پڑھتے تھے یا کچھ حصہ اس کا اُنہوں نے یاد کر لیا تھا.مگر معنے نہ جانتے تھے.ہاں اُنہوں نے کچھ تفسیریں علماء کی یاد کر چھوڑی تھیں اور موقع بے موقع لوگوں کو وہ تفسیریں سنا سنا کر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ صُحفِ بنی اسرائیل کے سچے مضامین بیان کر رہے ہیں.گویا صرف جہّال کا ذکر اس آیت میں تھا مگر آیت زیرِ تفسیر میں جُہّال کا ذکر نہیں بلکہ علماء کا ذکر ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اُن یہودیوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے عذاب نازل ہو گا.جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں علماء کا ذکر ہے نہ کہ جُہّال کا.اِس پرسوال ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کو فَاء سے کیوں شروع کیا گیا جس کے معنے ’’ پس‘‘ کے ہیں اور پس کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ پہلے مضمون کے نتیجہ میں یہ دوسرا مضمون پیدا ہوا ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم پر چونکہ لاتعداد مضامین بیان کرنے کی ذمہ واری ہے اِس لئے ایسی عبارت میں نازل کیا گیا ہے جو اختصار کا کمال اپنے اندر رکھتی ہے.پہلی آیت میں جُہّال کا ذکر تھا جو علماء کی غلط سلط تفسیروں پر اعتماد کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے اور دوسری آیت میں اُن لوگوں کا ذکر کیا جانا مقصود تھا جو عالم ہوتے ہوئے سچی دینداری سے عاری تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے.اگر مستقل طور پر اُن لوگوں کا ذکر کیا جاتا تو عبارت لمبی ہو جاتی.پس اﷲ تعالیٰ نے پہلی
Page 234
آیت میں جُہّال کا ذکر کیا اور دوسری آیت میں اُس کے تابع علماء کا ذکر کر دیا اور یوں فرما دیا کہ وہ جُہّال جن کا پہلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے علماء کی غیر ذمہ وارانہ حرکات کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں.اوّل علماء نے اُنہیں کتاب سے واقف نہیں کیا.دوسرے غلط سلط باتیں کتاب کی طرف منسوب کر کے اِن جُہّال کو یاد کرا دیں اور کہہ دیا کہ یہی تمہاری کتاب کا مفہوم ہے.پس اُن جُہّال کی تباہی اور بربادی کی ذمہ واری اُن علماء پر ہے اور ان کی گمراہی کا موجب اُن کی یہ بے ایمانی ہے کہ اپنے خیالات کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اُسے خدا تعالیٰ کی کتاب اُنہوں نے قرار دے دیا.پس مذکورہ بالا جُہّال کو جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی مگر ساتھ ہی یہ علماء بھی اُن کی گمراہی کے ذمہ وار قرار دئے جا کر اپنے گناہوں کے علاوہ اُن جہلاء کے گناہوں کی سزا میں بھی حصہ دار ہوں گے.اسی وجہ سے جُہّال کا ذکر کرنے کے بعد فرما دیا.’’ پس عذاب نازل ہو گا اُن لوگوں پر جو کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اﷲ کی طرف سے ہے.‘‘ اور اِس طرح مختصر الفاظ میں ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ یہود میں عالم بھی موجود ہیں مگر وہ اپنے علم سے ناجائز فائدہ اُٹھاتے ہیں.دوسرے یہ بتا دیا گیا کہجُہّال کی گمراہی کی ذمہ داری اِن علماء پر ہے.اور تیسرے یہ بتا دیا گیا کہ جُہّال کو اُن کے عمل کی جو سزا ملےگی اِس میں علماء بھی اُن کو گمراہ کرنے کی وجہ سے شریک کئے جائیں گے کیونکہ گمراہی کے ذمہ وار وہی ہیں.اتنے وسیع مضمون کو علماء کا ذکر پیچھے رکھ کر اور اُن کے ذکر سے پہلے صرف فاء کا حرف بڑھا کر ادا کر دیا گیا ہے.لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا.اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ علماء دنیوی اغراض کے ماتحت دین کو بگاڑتے ہیں اور اُن کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ دین چاہے برباد ہو جائے ان کو دنیا مل جائے.یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ لکھا تو ہاتھ سے ہی جاتا ہے پھربِاَيْدِيْهِمْ کا لفظ کیوں بڑھایا گیا؟ اِس کا جواب یہ ہے کہ اَیْدِیْ کا لفظ تاکید کے لئےبڑھایا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کَتَبَ کا لفظ کبھی لکھوانے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے جیسا کہ رسول کریم صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم نے فرمایا اَکْتُبُ لَکُمْ کِتَا بًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَ ہٗ اَبَدًا ( بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی صلی اﷲ علیہ وسلم و وفاتہٗ)میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ میں تمہیں ایک عبارت لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو.قرآن کریم سے بھی اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلے اﷲ علیہ و آلہٖ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے پس اَکْتُبُ کا لفظ جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے اس کے معنے لکھوانے کے ہیں.پس اِس جگہ پر اَیْدِیْھِمْ کے الفاظ بڑھا کر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اِس آیت میں علماء کا ذکر ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے تاکہ کوئی شخص یہ دھوکا نہ کھائے کہ
Page 235
شاید اس آیت میں بھی پہلے گروہوں کا ہی ذکر ہے اور لکھنے سے مراد لکھوانا ہے.فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ.اس میں بتایا ہے کہ یہ علماء تہرے عذاب کے مستحق ہیں.ایک وجہ تو اُن کے عذاب کی پہلے بتائی جا چکی ہے کہجہّال کو گمراہ کرتے ہیں دوسری وجہ اُن کے عذاب کی یہ ہو گی کہ انہوں نے خدائی کلام کی طرف غلط باتیں منسوب کیں اور تیسری وجہ عذاب کی یہ ہو گی کہ اس حرکت کا محرک بھی نیک نہیں تھا بلکہ اُن کا مقصد اس تحریف سے صرف دنیا کمانا تھا پس ایک عذاب تو اُن کو فعلِ بد کی وجہ سے ملے گا اور ایک عذاب محرّکِ بد کی وجہ سے ہو گا.اِس آیت میں سزا و جزاء کا ایک اہم فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے.فعلِ بد دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) فعلِ بد جو نادانی سے کیا جائے(۲) ٰفعلِ بد جو دیدہ دانستہ کیا جائے.پھر یہ فعل آگے دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) وہ فعلِ بد جس کا محرک نیکی کا خیال ہو خواہ غلط خیال ہو (۲)وہ فعلِ بد جس کا محرک خود ایک ذلیل اور گندہ جذبہ ہو.مثلاً کوئی شخص قتل کرتا ہے اور وہ قتل اس سے ناواقفی میں ہو جاتا ہے تو یہ فعلِ بد تو ہے لیکن یا تو اس کا مرتکب کلّی طور پر بَری قرار دیا جائے گا یا جب اُس نے پوری احتیاط سے کام نہ لیا ہو تو جزوی طور پر بری قرار دیا جائےگا.لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہو سکتا ہے جس نے دیدہ و دانستہ قتل کیا مگر فرض کرو اس وہم کے ماتحت قتل کیا کہ یہ شخص میرے بچوں کو قتل کرنے والا ہے یا ہماری قوم کے فلاں بزرگ کو قتل کرنے والا ہے یا اُسے نقصان پہنچانے والا ہے.یہ فعل بھی ہو گا تو بُرا مگر اس کا محرک نیک ہو گا.ایک اور تیسرا شخص ایسا ہو سکتا ہے جو کسی شخص کو اس لئے قتل کر دیتا ہے کہ اس کا روپیہ چھین کر عیّاشی کرے.اس شخص کا فعل بھی بُرا اور اُس کا محرک بھی بُرا.پس یہ دوگناہوں کا مرتکب ہوتا ہے قتل کا بھی اور حرص و ہوا کا بھی.اور اس لئے دوہرے عذاب کا مستحق ہو گا.اس کے اُلٹ نیکیوں کا بھی یہی حال ہے اور اس کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں.پس قرآن کریم کے اس جملہ میں کہ اُن پر عذاب ہو گا اُس تحریر کی وجہ سے جو اُن کے ہاتھوں نے لکھی اور اُن پر عذاب ہو گا اُ س دنیوی مال کی وجہ سے جو انہوں نے کمایا.اخلاق کے اِس لطیف نکتہ کو بیان کیا گیا ہے اور جو شخص تقویٰ حاصل کرنا چاہے اُس کے لئے علم کا ایک دروازہ کھول دیا گیا ہے.مسیحی اِس آیت سے یہ نتیجہ نکالا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے نزدیک رسول کریم صلے اﷲ علیہ وسلم کے زمانہ تک بائبل اپنی اصلی شکل میں موجود تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو محرف مبدّل بائبل کے بدلنے پر اعتراض کیوں کیا جاتا.اِس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو ہم نے اس آیت کے معنے بائبل کے بدلنے کے نہیں کئے اس لئے یہ نتیجہ ہمارے معنوں کو مدِّ نظر رکھتے ہوئے نہیں نکالا جا سکتا ( اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نزدیک بائبل قرآن کریم کے وقت میں
Page 236
محرف مبدّل نہ ہوئی تھی کیونکہ ہمارے علم اور تحقیق میں یقیناً اُس وقت تک بائبل محرف مبدّل ہو چکی تھی.میرا مطلب صرف یہ ہے کہ اس آیت کے معنے میں نے یہ نہیں کئے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ بائبل حضرت مسیح ؑ کے زمانہ سے بھی پہلے محرف مبدّل ہو چکی تھی ) لیکن اگر آیت کے یہ معنے کئے جائیں کہ یہودی لوگ بائبل کو بدلا کرتے تھے تو بھی اِس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ بائبل قرآن کریم کے زمانہ تک محرف مبدّل نہیں تھی کیونکہ اس صورت میں اس آیت کا مفہوم تو یہ ہو گا کہ یہودی بائبل کو بدلتے ہیں اور جب اس آیت کے یہ معنے کئے جائیں کہ یہودی بائبل کو بدلا کرتے ہیں تو اس فقرہ سے کونسا عقلمند یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہودی بائبل کو بدلا نہیں کرتے تھے اور بائبل اُس وقت تک محرف مبدّل نہیں ہوئی تھی بے شک یہ اعتراض اُن کی طرف سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر بائبل کی تعلیم محرف مبدّل تھی تو اس کے بدلنے میں حرج کیا تھا اور اس پر ڈانٹا کیوں گیا؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ گویہودی قرآن کریم کے نزول سے پہلے بائبل میں تحریف و تبدیل کرنے لگ گئے تھے تو بھی اُن کا اس کام کو جاری رکھنا بُرا تھا.بائبل کی نسبت تو بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک محرف مبدّل کتابِ آسمانی ہے.اگر کسی سَو فیصدی انسانی بنائی ہوئی کتاب کو کوئی شخص غلطی سے خدائی کتاب سمجھتا ہو اور یہ سمجھتے ہوئے پھر اُس میں کوئی تبدیلی کرتا ہو تو وہ شخص بھی مجرم سمجھا جائے گا اس لئے نہیں کہ وہ ایک آسمانی کتاب کو بدلتا ہے بلکہ اس لئے کہ جس کتاب کو وہ آسمانی سمجھتا ہے اُسے کیوں بدلتا ہے قرآن کریم میں صاف آتا ہے کہ منافق لوگ رسول کریم صلے اﷲ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے نَشْھَدُ اِنَّکَ لَرَسُوْلُ اللہِ.اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ١ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.( المنافقون:۲)یعنی منافق رسول کریم صلے اﷲ علیہ وسلم کو آ کر کہتے تھے کہ ہم خدا کی قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں کہ تو اﷲ کا رسول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تو اللہ کا رسول ہے مگر منافق اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں.اِن آیات میں منافقوں کو ایک ایسی بات کہنے پر جھوٹا کہا گیا ہے جو سچی ہے اور جس کے سچا ہونے پر خدا تعالیٰ خود بھی گواہی دیتا ہے.اُنہیں جھوٹا اِس لئے کہا گیا ہے کہ وہ دل سے اس بات کو نہیں مانتے تھے.جس طرح دل نہ مانتے ہوئے ایک سچی بات پر ظاہر میں ایمان کا اظہار کرنا منافقت اور بے ایمانی ہے اِسی طرح غلط کتاب کو آسمانی سمجھتے ہوئے اس میں بگاڑ پیدا کرنا بے ایمانی اور کُفر کی علامت ہے اور یقیناً یہ جرم اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر خدائی کتاب میں تنبیہ کی جائے.ایک عورت ہوش میں اپنے بچے کو قتل نہیں کرتی.اگر ایک عورت ایک ایسے بچے کو جسے وہ اپنا بچہ سمجھتی ہے گو درحقیقت وہ اُس کا بچہ نہیں قتل کرتی ہے تب بھی ہم یہی یقین کریں گے کہ اُس عورت کا دماغ خراب ہے کیونکہ گو وہ اُس کا بچہ نہیں مگر وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ وہ اُس کا بچہ ہے.اِسی طرح گو رسول کریم صلے اﷲ علیہ وسلم کے
Page 237
زمانہ کی بائبل محفوظ نہیں تھی اور محرف و مبدّل تھی مگر یہودی تو اُس کو غیر محفوظ اور محرف مبدّل نہیں سمجھتے تھے.جب وہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک خدا تعالیٰ کی کتاب سمجھتے تھے تو اُن کا اس کے مضامین پر پردہ ڈالنا یا اُن میں کوئی خرابی پیدا کرنا اُن کی بے ایمانی اور بد اعمالی کی واضح دلیل تھا.اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیئے کہ بائبل میں اُس کی موجودہ شکل میں بھی ہزاروں صداقتیں پائی جاتی ہیں پس اُن کے بدلنے سے اب بھی حق کو نقصان پہنچتا ہے.اِس آیت کا ایک اَور مفہوم بھی ہے اور وہ یہ کہ بائبل کے متعلق یہود کا یہ یقین ہے کہ بخت نصر کے زمانہ میں وہ ضائع ہو گئی تھی پھر عزرانبی نے اُس کو دوبارہ لکھا گویا یہودی تاریخ کے مطابق بھی اصلی بائبل موجود نہیں رہی تھی بعض انسانوں نے خواہ وہ نبی ہی ہوں اُس کو دوبارہ درست کر کے لکھا پس اُس کی حیثیت محض ایسی رہ گئی جیسا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی حدیثوں کی.اور جس طرح احادیث نبویہؐ کو کتاب اﷲ نہیں کہا جا سکتا اُس کو بھی کتاب اﷲ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اِس میں غلطی کے امکان پیدا ہو گئے خصوصاً جبکہ بائبل کو حفظ کرنے کا رواج کبھی بھی بنی اسرائیل میں نہیں ہوا اور خصوصاً جبکہ خود بائبل کی اندرونی شہادتیں اِس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ بائبل اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں بلکہ اُس میں بہت سے حواشی اور تفسیریں اور غلط روایتیں شامل ہو گئی ہیں.پس اس آیت کے یہ بھی معنے ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی تاریخوں کے مطابق خود جانتے ہیں کہ یہ کتاب انسانی دست بُرد سے پاک نہیں لیکن باوجود اِس کے اصرار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ خدائی کتاب ہے بے شک ابتدامیں یہ خدائی کتاب تھی مگر اب جبکہ اس میں انسانی دستبرد سے کچھ زیادتیاں یا کمیاں پیدا ہو گئی ہیں اِسے خالص خدا کا کلام کہنا اور الہامی کتاب کے مقابلہ میں پیش کرنا زیادتی اور ظلم ہے.عیسائی تو یہودیوں سے بھی ایک قدم آگے ہیں.سب کی سب انجیل خدا کی کتاب کہلاتی ہے.لیکن جب اُسے کھول کر پڑھنا شروع کرو تو لکھا ہوتا ہے متی کی انجیل.مرقس کی انجیل.لوقا کی انجیل.یوحنا کی انجیل.پطرس کے خط.پولوس کے خط.زید کے خط اور بکر کے خط.یہ انسانوں کی اناجیل اور زید اور بکر کے خطوط خدا کا کلام کس طرح ہو گئے.بے شک انجیل میں خدا کا کلام بھی موجود ہے مگر وہ خدا کی کتاب نہیں کہلا سکتی کیونکہ انسانوں نے اپنے الفاظ میں بعض باتیں لکھی ہیں جو انہوں نے خدا سے نہیں بلکہ خدا کے نبی سے سُنیں یا خدا کے نبی سے بھی نہیں سُنیں خدا کے نبی کی باتیں سن کر اُن سے ایک نتیجہ نکالا.اور یہ حصہ بھی باقی کتاب کا دو تین فی صدی ہے.باقی باتیں اپنے خیالات یا غیر محقق روایات پر مبنی ہیں.ایسی کتابوں کو خدا کی کتابیں کہنا اور پھر اُن پر مذاہب کی بنیاد رکھنا اور الہامی کتابوں کے مقابلہ میں اُن کو پیش کرنا ایک بہت بڑا ظلم ہے.
Page 238
اِس آیت سے اُن کتب کی طرف بھی اشارہ سمجھا جا سکتا ہے جو درجنوں کی تعداد میں یہود و نصاریٰ میں پائی جاتی ہیں اور الہامی کتب کہلاتی ہیں یا الہامی کتب کا درجہ رکھتی ہیں.لیکن خود مسیحی اور یہودی بھی اُن کی صداقت میں شک کرتے ہیں.عیسائیوں نے ’’ ایپو کریفا‘‘ کے نام سے ایسی کتابوں کا مجموعہ شائع کیا ہوا ہے.یہ سب کی سب کتابیں وہ ہیں جن کو اُن کے لکھنے والوں نے یا عیسائیوں کی بعض جماعتوں نے خدائی کتابیں قرار دیا ہے لیکن عیسائی بحیثیتِ مجموعی اُن کو خدائی کتابیں تسلیم نہیں کرتے اور سچی انجیلیں قرار نہیں دیتے جس قوم کے اپنے عقیدہ کے مطابق بھی ایسی اناجیل موجود ہیں جن کو خدائی کتابیں کہا جاتا ہے لیکن اُس قوم کے عقیدہ کے مطابق وہ خدا کی کتابیں نہیں ہیں کیا اُس کے افراد قابل ِ ملامت نہیں اور کیا قرآن کریم کا یہ کام نہ تھا کہ اُن کو زجر کرتا اور اُن کے اس عیب کو دنیا کے سامنے لاتا اور اُن مجرموں کی اصلاح کی کوشش کرتا.وَ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً١ؕ قُلْ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چند گنتی کے دنوں کے سوا (دوزخ کی )آگ ہرگز نہ چھوئے گی.تو (ان سے ) کہہ کیا تم نے اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗۤ اَمْ اللہ کی بارگاہ سے کوئی عہد لیا (ہوا) ہے (اگر ایسا ہے) تب تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا یا تم اللہ کے تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۰۰۸۱ متعلق ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں (کوئی )علم نہیں ہے حَلّ لُغَات.یُخْلِفُ.اَخْلَفَ سے مضارع کا صیغہ ہے اور اَخْلَفَ وَعْدَہٗ کے معنے ہوتے ہیں لَمْ یُتَمِّمْہُ عہد کو پورا نہ کیا.( اقرب) پس فَلَنْ یُّخْلِفَ عَھْدَہٗ کے معنے ہوں گے.وہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا.تفسیر.اس آیت میں اُن یہودیوں کا ذکر ہے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ یہود خواہ کچھ بھی کریں چونکہ وہ خدا تعالیٰ کے پیاروں کی اولاد ہیں وہ دائمی عذاب میں مبتلا نہیں کئے جا سکتے.حق تو یہ ہے کہ یہود نے بائبل میں سے حَیٰوۃُ بَعدَ الْمَمَات کے عقیدہ کو ہی غائب کر دیا ہے.عذاب و ثواب کا تو کوئی سوال ہی نہیں.سارا عہد نامۂ قدیم
Page 239
پڑھ جاؤ بڑی مشکل سے استنباطی طور پر حیات بعد الممات کاثبوت ملے گا.جس طرح قرآن کریم میں وضاحت سے حیات بعد الممات اور جزاو سزا کا ذکر ہے بائبل میں ایسا ہرگز نہیں.پس یہود کی اکثریت تو سارے انعام اِسی دنیا میں مانگتی تھی اور سزا بھی اِسی دنیا میں طلب کرتی تھی.کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پوری طرح جزا و سزا اور حشر و نشر کے عقیدہ سے آزاد نہیں ہو سکے تھے وہ لوگ بھی اپنے متعلق یہی خیال کرتے تھے کہ ہم کو کچھ زیادہ سزا نہیں ملے گی کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے پیارے ہیں اور اگر کوئی سزا ملی بھی تو وہ صرف چند دن کی ہو گی.اِن لوگوں میں سے بعض کا خیال تھا کہ اِس چند روزہ سزا کے بعد یہودیوں کو خاک کر دیا جائے گا اور اُن کی خاک نیکوں کے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے گی.اور بعض کا خیال تھا کہ یوں نہیں بلکہ یہود کو معاف کر دیا جائے گا.اِس عقیدہ کے بارہ میں یہود کے مختلف خیالات ذیل میں درج ہیں.سیل اپنے ترجمہ قرآن میں لکھتا ہے کہ یہود کے نزدیک یہ مسلّم مسئلہ ہے کہ کوئی یہودی خواہ کتنا ہی شریر ہو اور کسی فرقے کا ہو گیارہ ماہ اور حد سے حد ایک سال سے زیادہ تک دوزخ میں نہیں رہے گا سوائے داتھن ؔاور ایبی رام کے یادہریوں کے جو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے.داتھن اور ایبی رام وہ شخص ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تھی اور ایک جماعت بنا کر کوشش کی تھی کہ حضرت موسیٰ ؑ کی حکومت کو مٹا دیا جائے ( دیکھو گنتی باب ۱۶) اِن کو خدا تعالیٰ نے ایک خاص عذاب کے ذریعہ سے ہلاک کر دیا تھا.بابلی طالمود کے مطابق سوائے کافروں اورجیروبوم باقی سب یہودی بارہ مہینے تک دوزخ میں رہیں گے پھر جلا کر راکھ کر دیئے جائیں گے اور اُن کی خاک اُڑا کر نیکوں کے قدموں میں ڈال دی جائے گی.بابامیزیہ (BABA MEIZYA)کی طالمود میں لکھا ہے کہ تمام یہود جو دوزخ میں جائیں گے پھر نکل آئیں گے سوائے تین قسم کے آدمیوں کے.اوّل بدکار.دوسرے ہمسایہ کی عصمت دری کرنے والا.تیسرے ہمسایہ کو بدنام کرنے والا.ایروبین طالمود میں لکھا ہے کہ دوزخ کی آگ یہودی گنہگاروں کو نہیں چھوئے گی کیونکہ وہ دوزخ کے دروازہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خدا کی طرف واپس لوٹ آئیں گے.برکوت طالمود (BARAKOT) میں لکھا ہے مرتد اور رومی اور ایرانی دوزخ میں جائیں گے یعنی یہودی گنہگار دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں.اِس طالمود میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیلیوں کو دوزخ سے بہت کم خطرہ ہے ہاں مرتدیہودی کو دوزخ میں جانے کا خطرہ ہے.اِسی طرح غیر یہودیوں کے لئے خطرہ ہے.(جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Jehanna)
Page 240
اِن حوالجات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہودیوں کو بہت محدود سزا ملے گی اور اَیَّامًامَّعْدُوْدَۃ کے بھی یہی معنے ہیں، گنتی کے دنوں سے مراد مقررہ دن نہیں بلکہ تھوڑے دن مراد ہیں.یہ محاورہ اُردو میں بھی ہے کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ گنتی کی چیزیں ہیں.مطلب یہ کہ بہت تھوڑا مال ہے.بحرِمحیط نے اِس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ یہود کا خیال تھا کہ بچھڑے کی پوجا چونکہ چالیس دن کی گئی تھی اِس لئے اِسی قدر عذاب ہمیں ملے گا.بعض نے چالیس دن کے عذاب کو بھی زیاہ قرار دے کر کہا ہے کہ صرف سات دن یہود کو عذاب ملے گا.اِس سے پتہ لگتا ہے کہ یہود میں اس قسم کے خیالات اسلامی زمانہ تک بھی قائم رہے تھے.اﷲ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے رسولؐ ! تو اُن سے پوچھ کیا تم نے اﷲ تعالیٰ سے اِس بارہ میں کوئی عہد لیا ہے.اگر ایسا ہے تو اﷲ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور عذاب دینا یا نہ دینا تو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ تمہارے کاہنوں اور رُہبانوں سے تعلق نہیں رکھتا کہ وہ جو چاہیں فیصلہ کر دیں اگر خدا نے یہود کے متعلق کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے تو وہ بائبل میں موجود ہونا چاہیے.حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دوسرے نبیوں کی معرفت اُس کا اعلان ہونا چاہیے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی تو خاموش ہیں اور طالمود کے علماء اپنی قیاس آرائیوں سے اس بارہ میں فیصلہ کرتے ہیں کیا یہ خدا اور اُس کے دین کی ہتک نہیں؟ پھر فرماتا ہے اگر یہ عہد والی بات نہیں تو اس کے معنے یہ ہیں کہ تمہارے علماء اپنے ذہن اور اپنے خیال سے یہ باتیں بناتے ہیں اور یہ ظاہر بات ہے کہ اپنے ذہن اور اپنے خیال سے خدا تعالیٰ کے متعلق باتیں بنا لینا بہت گناہ ہے.حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مختلف ادیان میں بگاڑ اِسی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ لوگوں نے مختلف امور میں اپنی طرف سے قیاس آرائیاں کر کے مختلف ادیان کی طرف منسوب کرنی شروع کر دیں.آج مسلمان بھی ہر مسئلہ میں جس میں اُنہیں دوسروں سے اختلاف ہوتا ہے اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لئے اسلام کی آڑ لے لیتے ہیں.قرآن ساکت ہوتا ہے.حدیث خاموش ہوتی ہے بلکہ بعض دفعہ تو وہ مخالف ہوتے ہیں لیکن یہ رٹ برابر لگی چلی جاتی ہے کہ اسلام یُوں کہتا ہے اسلام کی تعلیم یُوں ہے.اﷲ تعالیٰ مسلمانوںکو اِس بات کے سمجھنے کی توفیق دے کہ وہ قرآن کو پارہ پارہ نہ کریں اور خدا تعالیٰ کے فرض کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں.
Page 241
بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ کیوں نہیں؟ جو لوگ بھی کسی قسم کی بدی کمائیں گے اور ان کا گناہ انہیں (چاروں طرف سے) گھیرلے گا وہ دوزخ اَصْحٰبُ النَّارِ١ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۰۰۸۲ (میں پڑنے )والے ہیں.وہ اُس میں (پڑے) رہیں گے.حَلّ لُغَات.کَسَبَ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں جَمَعَہٗ کسی چیز کو جمع کر لیا.اور کَسَبَ الْاِثْمَ کے معنے ہوتے ہیں تَحَمَّلَہٗ.گناہ کمایا.(اقرب)پس کَسَبَ سَیِّئَۃً کے معنے ہوں گے.گناہ کیا یا گناہوں کو اکٹھا کر لیا.تفسیر.بَلٰی کے معنے ایجابی ہوتے ہیں خواہ اِس سے پہلی عبارت میں نفی کا پہلو ہو یا اثبات کا.یوں اِس کے معنے’’ہاں‘‘ کے ہوتے ہیں مگر عام طور پر تو ہاں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پہلی بات ٹھیک ہے.لیکن جب بَلٰیکا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ بَلٰی کے بعد جو بات بیان کی گئی ہے وہ ٹھیک ہے.پہلی بات ہو سکتا ہے کہ غلط ہو اور ہو سکتا ہے کہ غلط نہ ہو.پس بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّ اَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓـَٔتُهٗ کے معنے یہ ہوئے کہ اِس حقیقت میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بدی کرتا ہے اور پھر اُس کی بدی اُس کا احاطہ کر لیتی ہے یعنی اتنی غالب آ جاتی ہے کہ نیکیوں کا اثر کمزور پڑ جاتا اور ضائع ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ دوزخ کے ساکن ہو جاتے ہیں اور اُن کی حالت اِس بات کی مستحق ہوتی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصہ تک اُس میں رہیں.دو شرطیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں یعنی بدی کمائے اور غلطی اُس کو گھیرلے.اِن سے اِس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر بدی انسان کو دوزخ کا مستحق نہیں بناتی بلکہ (۱) علم ہو (۲) ارادہ ہو (۳) نیکی پر بدیاں غالب آ جائیں تب انسان دوزخ کا مستحق ہوتا ہے.یہی وہ تعلیم ہے جو انسان کے لئے تسلی کا موجب ہو سکتی ہے ورنہ نصاریٰ کا کفّارہ جس میں صرف مسیح ؑ کی صلیبی موت پر ایمان لانے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا یہود کا دعوٰئے فضیلت جو ہر صورت میں اُن کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے یا ہندوؤں کی محدود نجات جو بار بار انسان کو تناسخ کے چکّر میں ڈالتی ہے یا زرتشتیوں کا نسلی فضیلت کا دعویٰ یہ سارے کے سارے قابلِ اعتراض ہیں.قرآن کریم کہتا ہے کہ مذہب ایک ذریعہ نجات کا ہے کسی مذہب کے قبول کرنے کے یہ معنے نہیںکہ اُس مذہب کے قبول کر لینے سے خاص حقوق قائم ہو گئے ہیں.قانونِ نجات کی بنیاد بہر حال اس امر پر ہے کہ نیک علم،نیک ارادہ اور نیک کوشش کے ساتھ کام کرو تو تمہیں
Page 244
نتیجہ تو اُس کو اِس دنیا میں مل گیا لیکن خدا تعالیٰ کی خاطر نیک کام کرنے کا نتیجہ اُس کو اِس دنیا میں نہیں ملا وہ نتیجہ مرنے کے بعد جنّت کی صورت میں ملے گا.اگر کسی شخص نے خدا تعالیٰ کی خاطر نیک کام کیا ہے تو جہاں تک نیک کام کا تعلق ہے وہ بنی نوع انسان کے فائدہ کی چیز ہے.بنی نوع انسان اپنے محدود ذرائع سے اُس کو محدود انعام اسی دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن جہاں تک خدا تعالیٰ کی خاطر نیک کام کرنے کا تعلق ہے وہ دنیوی انعام اُس کا بدلہ نہیں کہلا سکتا اُس کا بدلہ خدا تعالیٰ پر الگ واجب ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ کے ذرائع غیر محدود ہیں وہ اُس کے بدلہ میں اُس نیک شخص کو غیر محدود جنّت دیتا ہے پس اٰمَنُوْا کی شرط لگا کر عملِ صالح کی قیمت نہیں گھٹائی بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ عملِ صالح کے ساتھ جب ایمان لگ جائے تو اُس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اسی دنیا میں نہیں بلکہ اگلے جہان میں بھی اُس کا انعام ملتا ہے پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عملِ صالح کی قیمت گراتا ہے وہ غلطی کرتے ہیں.عملِ صالح تو انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور انسان اس کی قیمت ادا کرتے ہی رہتے ہیں.قرآن کریم کا اصل تعلق تو اُس عملِ صالح سے ہے جو خدا کی خاطر کیا جائے وہ یہ نہیں کہتا کہ عملِ صالح کا جب تک ایمان اُس کے ساتھ نہ ہو کوئی بدلہ نہیں ملنا چاہیے وہ تو اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسانوں کے لئے جو نیک کام کئے جائیں انسانوں کو اُن کا بدلہ دینا چاہیے اور قانونِ قدرت بھی اُن کے مناسب بدلہ کا انتظام کر دیتا ہے لیکن آیت زیر تفسیر اور اِسی قسم کی دوسری آیتوں میں وہ یہ زائد مضمون بیان کرتا ہے کہ جب کوئی شخص نیک عمل کرتے وقت یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ کام خدا کی خاطر کر رہا ہوں اور جس کے سامنے خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے کلام اور اُس کے رسول ؐ کی ہدایت کے مطابق نیک عمل کی ایک کامل صورت آجاتی ہے تو ایسے شخص کی جزاء یقیناً اُس پہلے شخص کی جزاء سے زیادہ ہونی چاہیے اور صرف اِسی دنیا میں اُسے جزاء نہیں ملنی چاہیئے بلکہ اگلے جہان میں بھی ملنی چاہیے کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل کو وابستہ کر دینے کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنے کی وجہ سے جزا ء کی کمیّت اور اُس کے زمانہ کی وسعت لازماً ممتد ہو جاتی ہے.عملِ صالح.قرآن کریم جہاں بھی کہتا ہے عملِ صالح کہتا ہے.عملِ صالح کے معنے ہیں مناسبِ حال عمل یعنی نماز کے موقع پر نماز.روزہ کے موقع پر روزہ.زکوٰۃ کے موقع پر زکوٰۃ اور جہاد کے موقع پر جہاد.صرف نیک عمل انسان کے لئے نفع بخش نہیں ہو سکتا بلکہ مناسبِ حال عمل نفع بخش ہوتا ہے.دوسرے عملِ صالح نے اِس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اچھا فعل بھی بعض جگہ بُرا ہو جاتا ہے.رحم کی جگہ انتقام اور انتقام کی جگہ رحم بھی مضر ہے پس رحم گو اچھا ہے مگر انتقام کے موقع پر رحم عملِ صالح نہیں ہو گا اور اِس لئے ناپسند یدہ فعل ہو گا.جہاد کے موقع پر کوئی شخص نماز
Page 245
پڑھنے بیٹھ جائے تو نماز گو اچھی چیز ہے مگر اُس وقت عملِ صالح نہیں ہو گا اور اِس لئے نفع بخش ثابت نہیں ہو گا.اَصْحٰبُ النَّار اور اَصْحٰبُ الْجَنْۃِ فرما کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک عارضی عذاب پانے والے اور ایک لمبا عذاب پانے والے.ایک مستقل جنّت والے اور ایک عارضی جنت والے.اصحاب کا لفظ ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے جب نسبت مستقل ہو.پس قرآنی اعتبار سے اَصْحٰبُ النَّار وہ ہیں جن کا لمبا تعلق دوزخ سے ہو اور اَصْحَابُ الْجَنَّۃ وہ ہیں جن کا لمبا تعلق جنت سے ہو.ان کے علاوہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا دوزخ سے بھی اس قدر لمبا تعلق نہیں ہو گا جس قدر پہلے لوگوں کا.یا جنت سے بھی اس قسم کا لمبا تعلق نہیں ہو گا جس قسم کا پہلے لوگوں کا.قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عارضی عذاب والے یا عارضی جنت والے پہلے کچھ عذاب پا لیں گےاور پھر اپنے اپنے وقت پر معافی حاصل کر کے جنت میں داخل کر لئے جائیں گے جو مستقل ہو گی.پس اَصْحٰبُ الْجَنْۃِ کے معنے ہیںجو پہلے دن سے ہی جنّت میں جائیں ورنہ یُوں تو ہر شخص ہی آخر میں جنّت میں چلا جائے گا.آریہ قوم کی تعلیم اِس کے خلاف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے خدا عذاب دے گا اور پیشتر اِس کے کہ عذاب مکمّل ہو انسان کو انعام دینا شروع کر دے گا کچھ مدّت انعام دے کر پھر جو گناہ بچا کر رکھ لئے جائیں گے اُن کی سزا میں دوبارہ اس کو کسی جون میں ڈال دیا جائے گا.یہ تعلیم کینہ پر اور بُغض پر دلالت کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کینہ اور بُغض سے پاک ہے.وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اور (اس وقت کو بھی یاد کرو ) جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اللّٰهَ١۫ وَ بِالْوَالِدَيْنِ۠ اِحْسَانًا وَّ ذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ اور والدین سے احسان (کا معاملہ) کرو گے اور (اسی طرح) قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور الْمَسٰكِيْنِ وَ قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا (یہ عہدبھی لیا تھا )کہ لوگوں کے ساتھ ملاطفت کے ساتھ کلام کیا کرو اور نما ز کو قائم رکھاکرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو مگر
Page 246
الزَّكٰوةَ١ؕ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ۰۰۸۴ (اس کے بعد )تم میں سے چند ایک کے سوا باقی سب (کے سب )اعراض کرتے ہوئے پھر گئے.حَلّ لُغَات.مِیْثَاقٌ.اَلْمِیْثَاقُ عَقْدٌ مُؤَکَّدٌ بِیَمِیْنٍ وَّعَھْدٍ.مِیْثَاقٌ کے معنے ہیں ایسا عہد کرنا جو قسم سے مؤکد ہو.(مفردات) تفسیر.گزشتہ کئی رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اُن افعالِ شنیعہ کا ذکر کیا تھا جن کا ارتکاب انہوں نے اپنے انبیاء کے مقابلہ میں کیا.اور بتایا تھا کہ یہود کی ان متواتر نافرمانیوں کی وجہ سے ابراہیمی وعدۂ نبوت بنو اسحاق کی بجائے بنو اسمٰعیل کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے.حقیقت یہ ہے کہ یہود صرف اس وجہ سے مجرم نہیں تھے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اسلام اورمسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا بلکہ اُن کے جرموں کا ایک لمبا سلسلہ تھا جس کی بنا پر آخر نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسمٰعیل کی طرف منتقل ہو گئی.اگر صرف اس آخری جرم کی وجہ سے اُن کو نبوت سے محروم کیا جاتا تو بے شک یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ صرف ایک جرم کی وجہ سے بنی اسرائیل کو نبوت سے کیوں محروم کر دیا گیا.مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کے جرائم کا ایک لمبا سلسلہ بیان فرما کر اس اعتراض کو دُور کر دیا اور بتادیا کہ تمہارے پے در پے گناہوں نے تمہیں اس سزا کا مستحق ٹھہرایا ہے کہ تم کو اس نعمت سے محروم کر دیا جائے.پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنو اسحاق میں نبوت کا اجراء اُن کی کسی ذاتی فضیلت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ابراہیمی وعدوں کی وجہ سے تھا.جب انہوں نے ابراہیمی عہد کو پس ِ پشت پھینک دیا تو محض بنو اسحاق کا ایک فرد ہوناانہیں نبوت کے انعام کا مستحق نہیں بنا سکتا تھا.اس کے بعد قرآن کریم نے انہیںبتایا کہ تمہارے جرم اب بھی کچھ کم نہیں.اس رسول کے آنے سے پہلے تمہاری قوم جو کچھ کیا کرتی تھی وہ تم نے اس رسول کے زمانہ میں بھی جاری رکھا ہے.اگر اب بھی تمہاری قوم میں سے کوئی نبی آجاتا تو تم اس سے بھی یہی سلوک کرتے.پس تمہارا یہ کہنا کہ ہمارے لیے اس رسول کی تعلیم حجت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بنی اسمٰعیل میں سے ہے درست نہیں کیونکہ تمہارا رویہ بتارہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اب بھی نبی بنا دیا جاتا تو تم اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے جیسا کہ تم پہلے آنے والے انبیاء سے کرتے رہے ہو.
Page 247
اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس اعلیٰ تعلیم کو جانے دو جس میں تمہیں اس رسول سے اختلاف ہے.تم صرف ان افعال کو زیربحث لائو جن کو تم بھی قومی اور اخلاقی ترقی کے لیے ضروری سمجھتے ہو اور بتائو کہ کیا تم ان پر کاربند ہو.چنانچہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور عہد بھی ایسا جو نہایت پختہ تھا.جس کے پورا کرنے پر انعام اور توڑنے پر سزا مقدر تھی.مگر کیا وہ عہدتم نے پورا کیا؟ اگر تمہارا اپنے مذہب پر بھی عمل نہیں رہا اور ہمارے رسول کا بھی تم انکار کر رہے ہو تو بتائو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تم کتنے بڑے مجرم ہو؟ اس آیت میں جس میثاق کا طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے کوئی خاص عہد مراد نہیں بلکہ مختلف عہد مراد ہیں جو بنی اسرائیل سے متفرق اوقات میں لئے جاتے رہے اور جن پر عمل کرنے کی بائیبل میں ان کو سخت تاکید کی گئی ہے.اسی لئے یہ احکام بائیبل میں کسی ایک جگہ بیان نہیں ہو ئے بلکہ متفرق مقامات میں اُن کا ذکر آتا ہے.قرآن کریم نے ان احکام کا اکٹھا ذکر اس لئے کیا ہے تاکہ ان کو یاد دلایا جا ئے کہ وہ اپنے مذہب سے کس قدر دُور جا چکے ہیں.مزید برآں قرآن کریم نے ان احکام کو ایک اعلیٰ درجہ کی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے.جو اس کے حُسن کو نمایاں کرنے والی ہے.اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود کی پرستش سے بائبل میں بہت سے مقامات پر روکا گیا ہے بلکہ یہ حکم خود مو سیٰ ؑ کےدَس احکام میں بھی پایا جاتا ہے چنانچہ خروج باب ۲۰ آیت۳ تا ۶ میں لکھا ہے:.’’میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا نہ ہو.تو اپنے لئے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں زمین کے نیچے ہے مت بنا.تو اُن کے آگے اپنے تئیں مت جھکا.اور نہ اُن کی عبادت کر کیونکہ میں خداوند تیر ا خدا غیّور خدا ہوں.اور باپ دادوں کی بدکاریاں اُن کی اولاد پر جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں تیسری اور چوتھی پشت تک پہنچاتا ہوں.پر اُن میں سے ہزاروں پر جو مجھے پیار کرتے اور میرے حکموں کو قبول کرتے ہیں رحم کرتا ہوں.‘‘ (۲) والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بھی انہیں احکام میں موجود ہے.چنانچہ خروج باب۲۰ آیت۱۲ میں لکھا ہے:.’’ توُ اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہووے.‘‘ اِسی طرح استثنا باب۲۱ آیت۱۸تا۲۱ میں بھی اس کا ذکر آتا ہے.لکھا ہے:.
Page 248
’’اگر کسی آدمی کا بیٹا گردن کش اورمگرا ہو جو اپنے باپ اور اپنی ماں کی آواز کو نہ سُنے.اوروے ہر چنداُسے تنبیہ کریں پر وہ ان پر کان نہ لگاوے.تب اُس کا باپ اور اس کی ماں اُسے پکڑیں اور باہر لے جا کے اُس شہر کے بزرگوں کے پاس اور اس جگہ کے دروازے پر لائیں اور وے اس شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا گردن کش اور مگرا ہے ہرگز ہماری بات نہیں مانتا.بڑاہی کھائو اور متوالا ہے.تو اس کے شہر کے سب لوگ اس پر پتھرائو کریں کہ وہ مر جائے.تو شرارت کو اپنے درمیان سے یوں دفع کیجیئو تاکہ سارا اسرائیل سُنے اور ڈرے.‘‘ (۳)ذی القربیٰ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر احبار باب ۱۹آیت۱۶تا۱۸ میں یوں آتا ہے: ’’تو عیب جوئیوں کی مانند اپنی قوم میں آیا جایا نہ کر.اور اپنے بھائی کے خون پر کمر نہ باندھ.میں خداوند ہوں.تو اپنے بھائی سے بغض اپنے دل میں نہ رکھ.تو البتہ اپنے بھائی کو نصیحت کر تاکہ ُتو اس کے سبب خطا کار نہ ٹھہرے.ُتو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلہ مت لے اور نہ ان کی طرف سے کینہ رکھ.بلکہ ُتو اپنے بھائی کو اپنی مانند پیار کر.میں خداوند ہوں.‘‘ یہ امریادرکھنا چاہیے کہ تورات میں تمام رشتہ داروں کے لئے عام طور پر بھائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے.(۴) بہو سے نیک سلوک کرنے کا ذکر خروج باب۲۱ آیت۹ میں اس طرح آتا ہے کہ ’’اگروہ اُس کی منگنی اپنے بیٹے کے ساتھ کردے تو وہ اُس سے بیٹوں کا سا سلوک کرے.‘‘ (۵) ہمسایہ سے نیک سلوک کا ذکر احبار باب۱۹آیت۱۳ میں آتا ہے.لکھا ہے: ’’ توُ اپنے پڑوسی سے دغا بازی نہ کر نہ اس سے کچھ چھین لے.‘‘ چونکہ ذوی القربیٰ سے ظاہری قرابت بھی مراد ہو سکتی ہے اس لیے ہمسایہ کا ذکر کر دیا گیا ہے.(۶)یتامیٰ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر استثنا باب۱۴آیت۲۹ میں آتا ہے.لکھا ہے:.’’مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں آویں اور کھاویں اور سیر ہو ویں تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے ہاتھ کے سب کاموں میں جو تو کرتا ہے تجھے برکت بخشے.‘‘ (۷)مساکین کے متعلق استثناباب۱۵ آیت۱۱ میں یوں حکم ہے کہ ’’مسکین زمین پر سے کبھی جاتے نہ رہیں گے.اس لئے یہ کہہ کےمیں تجھے حکم کرتا ہوں کہ توُاپنے بھائی کے واسطے اور اپنے مسکین کے لئے اور اپنے محتاج کے واسطے جو تیری زمین پر ہے اپنا
Page 249
ہاتھ کشادہ رکھیو.‘‘ (۸)تمام بنی نوع انسان سے نیک سلوک کرنے کا حکم خروج باب۲۳ آیت ۱ تا ۷ میں اس طرح ہے.’’ توکسی کی جھوٹی خبر مت اُڑا.ُ تو ظلم کی گواہی میں شریروں کا ساتھی مت ہو.توُ گروہ کی پیروی بدی کرنے میں مت کیجیئو اور توُکسی جھگڑے میں لوگوں کی بہتات کے سبب اُن کی طرف مائل ہو کے ناحق مت کیجیئو اور نہ کنگال کی اُس کے مقدمہ میں طرفداری کیجیئو اگر توُ اپنے دشمن کے بیل یا گدھے کو بے راہ جاتے دیکھے تو ضرور اُسے اُس کنے پہنچائیو.اگر توُاس کے گدھے کو جو تیرا کینہ رکھتا ہے دیکھے کہ بوجھ کے نیچے بیٹھ گیا اور تو اس کی مدد نہ کرنا چاہے تو البتہ اس کی کمک کر.توُاپنے محتاج سے اس کے مقدمہ میں انصاف کو مت پھیرئیو.جھوٹے معاملہ سے دور رہیو.اور بے گناہوں اور بچوں کو قتل مت کیجیئو.کیونکہ میں شریر کی تصدیق نہ کروں گا.‘‘ اسی طرح امثال باب۳ آیت۳۰ میں لکھا ہے.’’اگر کسی نے تجھے نقصان نہ پہنچایا ہو تو اُس سے بے سبب جھگڑا نہ کرنا.‘‘ (۹)نماز قائم کرنے کا حکم استثناء باب۱۳ آیت۴ میں یوں ہے کہ ’’چاہیے کہ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرو اور اس سے ڈرو اور اس کے حکموں کو حفظ کرو.اور اس کی بات مانو.تم اُسی کی بندگی کرو اور اسی سے لپٹے رہو.‘‘ اسی طرح استثنا باب۶آیت۱۳ میں لکھا ہے.’’تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اُسی کی عبادت کرنا اور اُسی کے نام کی قسم کھانا.‘‘ (۱۰)زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم خروج باب۲۳ آیت ۱۰،۱۱ میں یوں ہے.’’اور چھ برس زمین میں کھیتی کر اور اس سے جو پیدا ہو جمع کر.پر ساتویں برس اُسے چھوڑدے کہ پڑی رہے تاکہ تیری قوم کے مسکین اُسے کھاویں.اور جو اُن سے بچے میدان کے چار پائے چریں.ایسا ہی توُ اپنے انگور اور زیتون کے باغ کا معاملہ بھی کیجیئو.‘‘ مگرباوجود ان احکام کے یہود ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور ان کے سلوک اپنوں اور بیگانوں سے خراب ہو رہے تھے.یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرت عُزیر کو ابن اللہ قرار دینے لگ گئے تھے.جیسا کہ یہود کا صدوقی فرقہ جو یمن کی طرف رہتا تھا اس شرک میں ملوث ہو چکا تھا(الملل و النّحل زیر عنوان الکلام علی الیہود و علی
Page 250
من انکر التثلیث من نصاریٰ).اور بعض اپنے علماء کے ہر ایک حکم کو وحی الہٰی کے طور پر مانتے اور اپنی کتاب کے احکام کو پس پُشت پھینک دیتے.یتامیٰ اور مساکین کے ساتھ ان کا سلوک نہایت بُرا تھا.اور بنی نوع انسان کی ہمدردی اُن کے اندر نام کو بھی نہ تھی.عبادتوں میں سُست اور زکوٰۃ دینے سے جی چرُاتے تھے.جیسے آج کل کے مسلمان ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ تمام باتیں جو یہود کے متعلق خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں.یہود سے تو صرف یہ عہد لیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا.لیکن مسلمانوں پر خدا تعالیٰ نے اتنا فضل کیا کہ اسلام کی بنیاد ہی اس نے لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ پر رکھی.یعنی اس بات پر کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ قادرِ مطلق ہے.وہ ہر ایک کام خود کر سکتا ہے.اُس کو کسی کی مدد کی ہرگز ضرورت نہیں.مگر باوجود اس کے کہ اسلام کی بنیاد لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ پر رکھی گئی تھی آج مسلمانوں میں اس قدر شرک پایا جاتا ہے کہ اور قوموں میں اس کی نسبت بہت کم ہے.مسلمان قبروں پر بغیر کسی قسم کے حجاب کے اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ خدا کے آگے سجدہ کرنے والوں میں اور ان میں ذرہ بھی فرق نہیں رہ جاتا.مجھے اس بات پر ہمیشہ تعجب آیا کرتا تھا کہ کیا کوئی مسلمان بھی قبر پر سجدہ کر سکتا ہے؟ اور میں باوجود شہادتوں کے اس پر یقین نہیں کرتا تھا.لیکن ایک دفعہ جب ہم چند آدمی ہندوستان میں اسلامی مدارس دیکھنے کے لئے گئے تو لکھنؤ میں فرنگی محل کا مدرسہ دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا.اچھے لائق اور عالم اُستاد تھے.ہوشیار اور ذہین شاگرد معلوم ہوتے تھے لیکن اس مدرسہ اور دوسرے مدارس کو دیکھ کر جب ہم شام کو واپس اپنے مکان کی طرف آرہے تھے تو ایک قبر کے سامنے جو آدمی پورا پورا سجدہ کر رہا تھا وہ فرنگی محل کے مدرسہ کا ایک استاد تھا.مجھے اس کو دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس نے علم پڑھ کر بھی اس کی کچھ قدر نہ کی اور قبر پر سجدہ کرنے لگ گیا.مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اِن آیات میں اسی لئے یہود کا ذکر سنایا تھا کہ ایک دن تم بھی اسی طرح کرنے لگو گے.پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود سے ہم نے یہ بھی اقرار لیا تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا.یہ بات بھی اس زمانہ میں مسلمانوں سے بالکل مٹ گئی ہے.یہ تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے نیک سلوک کریں.ان کی پرورش کریں.اُن پر اپنا مال صرف کریں لیکن یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ اولاد بھی والدین پر احسان کرے اور اُن کی خدمت بجا لائے.اِسی طرح یہود سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ قریبیوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا.پھر تمام دنیا میں جس قدر لوگ ہیں ان کو نیک باتیں کہنا.یہ کیسی اچھی اور عمدہ تعلیم تھی.کوئی بوجھ نہ تھا.کوئی عقل کے خلاف بات نہ تھی لیکن جس طرح یہود نے ان احکام پر عمل ترک کر دیا تھا.اسی طرح مسلمانوں نے بھی ان
Page 251
احکام پر عمل ترک کر دیا.پھر حکم تھا کہ نمازیں پڑھو.لیکن دیکھ لو آج کتنے مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں.پھر حکم تھا کہ زکوٰۃ دو.مگر بہت تھوڑے ہیں جو اس کے پابند ہیں.اللہ تعالیٰ یہود کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ ان احکام کو سن کر پِھر گئے اور ان پر عمل نہ کیا.اسی طرح اب مسلمانوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احکام سے اکثر پِھر گئے.اسی طرح مسلمان ذوی القربیٰ کو شریکہ یعنی دشمنی کا باعث سمجھتے ہیں.اللہ تعالیٰ نے جن کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا تھا اُن سے دشمنی اور لڑائی جھگڑے کئے جاتے ہیں.یتیموں کے ساتھ ملاطفت اور نرمی کا حکم تھا لیکن ان کے اموال بڑی دلیری سے کھائے جاتے ہیں.مسکینوں کی خبر گیری اُن کا فرض تھا لیکن انہیں حقارت اور نفرت سے دیکھا جاتا ہے.تمام بنی نوع انسان کو نیک باتوں کی تلقین کرنا ان کا فرض تھا لیکن اس فرض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کی جاتی.وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم ہمیں کافر کہتے ہو مگر خودیہ کبھی سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ اُن کا اپنا عمل اسلام پر کہاں تک ہے.مجھے کئی غیر احمدیوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے.جب اس قسم کی بحث ہو تو میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں.وہ کہتے ہیں مسلمان.َمیں کہتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں.مگر آپ یہ بتائیں کہ کیا آج کل مسلمانوں میں اسلامی احکام پر عمل پایا جاتا ہے؟ اس پر انہیں اقرار کرنا پڑتا ہے کہ نہیں پایا جاتا.میں کہتا ہوں کہ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں میں حقیقت ِ اسلام نہیں رہی.ورنہ نام کے لحاظ سے تو وہ یقیناً مسلمان ہی ہیں اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا.پس جس طرح مسلمان جانتے ہیں کہ چوری ناجائز ہے.جھوٹ اور افترا ناجائز ہے.دوسروں کے حقوق غصب کرنا ناجائز ہے مگر پھر بھی وہ ان افعال کے مرتکب ہوتے ہیں.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود بالکل مطلب پرست اور مشرک ہو گئے تھے اور باوجود اس کے وہ مسلمانوں سے جو ان احکام پر بلکہ ان سے بڑے بڑے احکام پر عمل پیرا تھے لڑتے تھے.اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسٰی علیہ السلام کی صداقت کے متعلق تویہ عذرپیش کر سکتے ہو کہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے مگر تورات کے ان احکام کے متعلق کیا عذر کر سکتے ہو.تمہارا ان احکام کو تسلیم کرنا اور پھر اُن سے کلی طور پر اعراض اختیار کر لینا بتاتا ہے کہ اب تم میں صداقت باقی نہیں رہی.مگر جیسا کہ قرآن کریم کا طریق ہے اُس نے اس آیت میں بھی یہود کی بدیوں کا ذکر کرتے ہوئے اُن کی تمام قوم کو یکساں مجرم قرار نہیں دیا بلکہ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ فرما کر اُن میں سے جو نیک لوگ تھے اُن کو مستثنیٰ کر لیا ہے.اِس آیت کے متعلق یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں ہر جگہ ترتیب کے حسن کو قائم
Page 252
رکھا گیا ہے اسی طرح یہاں بھی ترتیب الفاظ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا گیا.سب سے پہلے لَاتَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰہَ میں واحد خدا پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم بیان کیا ہے کیونکہ توحید ایک بنیادی اصل ہے جو تمام انبیاء کا مشترک مشن تھا اور جس کے سمجھنے سے ہی باقی تمام مسائل سمجھے جا سکتے ہیں.اِس کے بعد وَ بِالْوَالِدَيْنِ۠ اِحْسَانًا کا حکم دے کر والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم بیان کیا ہے.کیونکہ والدین کا احسان خدا تعالیٰ کے احسان کا ظل ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ کا احسان حقیقی ہوتا ہے اور باقی سب احسان ظلّی ہوتے ہیں.اور چونکہ والدین بھی اپنی اولاد کے لئے خدا تعالیٰ کی صفات کے ایک رنگ میں مظہر ہوتے ہیں.اس لئے توحید کے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ حُسنِ سلوک کا ذکر فرما دیا.وَ بِالْوَالِدَيْنِ۠ اِحْسَانًاسے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ والدین سے سلوک بھی احسان کے معروف معنوں میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے.کیونکہ اس آیت میں احسان کا لفظ عام معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ ایک اور معنیٰ میں استعمال ہوا ہے.عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کسی امر کے بدلہ کے لئے بھی وہی لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے.جیسے ظلم کے بدلہ کا نام بھی ظلم رکھ دیا جاتا ہے اور اس سے مرادظلم نہیں ہوتا بلکہ اس کے معنے صرف ظلم کا بدلہ لینے کے ہوتے ہیں.جیسے اسی سورۂ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ.(البقرۃ :۱۹۵) یعنی جو شخص تم پر ظلم کرے تم اُس پر اُسی قدر ظلم کر سکتے ہو.اب یہ امر ظاہر ہے کہ ظلم کا اسی قدر بدلہ لینا ظلم نہیں کہلا سکتا.پس بدلہ لینے والے کے لئے جو اِعْتَدَاء کا لفظ استعمال کیا گیاہے اس کے معنے محض بدلہ کے ہیں نہ کہ ظلم کے.اسی طرح احسان کرنے والے کے حق میں جب احسان کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنے بدلۂ احسان کے ہوتے ہیں نہ کہ احسان کے لیکن احسان کرنے والوں کے سوا دوسرے لوگوں کی نسبت اس لفظ کا استعمال اپنے معروف معنوں میں ہوتا ہے.اس کے بعد ذوی القربیٰ کے ساتھ حسن ِ سلوک کا ذکر ہے.کیونکہ ماں باپ سے حسن ِسلوک کے بعد طبعاً ہر شخص اپنے رشتہ داروں سے حسنِ سلوک کرتا ہے اور وہ بھی والدین کی عدم موجودگی میں والدین ہی کے قائم مقام سمجھے جاتے ہیں.پھر عام لوگوں کو لیا ہے جن کا احسان حقیقی معنوں میں نہیں ہوتا بلکہ قومی معنوں میں ہوتا ہے.ان میں سے پہلے یتامیٰ کو لیا ہے.یہ خود محسن نہیں ہوتے لیکن ان کے ساتھ احسان اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ بوجہ اپنی کمزوری اور صغر سنی کے اپنے مطالبات کو خود پورا کروانے کی طاقت نہیں رکھتے.اور اُن کے حقوق کودلیری کے ساتھ غصب کر لیا جاتا ہے.پھر اس لئے بھی وہ محبت اور حسنِ سلوک کے مستحق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے سایۂ عاطفت سے
Page 253
بچپن میں ہی محروم ہو جاتے ہیں.اور اس وجہ سے وہ قوم کی ایک قیمتی امانت ہوتے ہیں.اگر اُن کی صحیح نگرانی کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، اُن کو آوارگی سے محفوظ رکھا جائے تو وہ قوم کا ایک مفید وجود بن جاتے ہیں.اور نہ صرف ان کی اپنی زند گی سنور جاتی ہے بلکہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی سنوارنے والے بن جاتے ہیں.ان کے بعد مساکین کا ذکر کیا.یہ لوگ گو محتاج ہوتے ہیں مگر سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی غربت کا پتہ لگنے نہیں دیتے.پس مساکین کا ذکر کر کے اس طرف توجہ دلائی کہ تمہیں یہ طریق اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو شخص تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے اس کی تو تم مدد کردو اور جو خاموش بیٹھا رہے اس کو تم نظر انداز کر دو.بلکہ تم ایسے لوگوں کی طرف بھی توجہ رکھو جو غربت کے باوجود اپنے وقار کو قائم رکھتے ہیں اور اخلاقی بلندی کا ثبوت پیش کرتے ہیں.اس کے بعدتمام بنی نوع انسان کی ہمدردی کا ذکر کیا.اور فرمایا.قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا.یہ لفظ حُسْنٌ اور حَسَنٌ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے.لیکن بعض نے فرق بھی کیا ہے.کہ اگر حَسَنٌ ہو تو مصدر محذوف کی صفت ہو گا.یعنی قُوْلُوْا لِلنَّاسِ قَوْلًا حَسَنًا.اور اگرحُسْنٌ ہو تو حذفِ مضاف ہو گا.یعنی قُوْلُوْا لِلنَّاسِ قَوْلًا ذَا حُسْنٍ (املاء) دونوں صورتوں میں اس کے معنے یہ ہیںکہ تم لوگوں کو ایسی باتیں کہو جو نہایت اچھی ہوں.عام بنی نوع انسان کو بعد میں اس لئے رکھا کہ یہ لوگ یتامیٰ اور مساکین کی طرح محتاج نہیں ہوتے بلکہ اپنی ضروریات کے آپ متکفل ہوتے ہیں.پس سب سے کم احتیاج رکھنے کی وجہ سے ان کو سب سے آخر میں رکھا.غرض ان تمام احکام میں ایک اعلیٰ درجہ کی ترتیب پائی جاتی ہے.ایک خدا کی پرستش کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا.ایک وہ جو بطور حق نیک سلوک کے مستحق ہیں اور دوسرے وہ جو بطور رحم کے مستحق ہیں.پہلوں کا مقدم ذکر کیا کیونکہ وہ ایک قرضہ کی ادائیگی کی سی صورت تھی.اور جو بطور رحم احسان کے مستحق تھے ان کو بعد میں رکھا.اور پھر جو شخص جس قدر رحم کا محتاج تھا اُسی درجہ پر اُس کا ذکر کیا.اِس کے بعد عبادات کو لیا.اور اُن میں سے بدنی اور مالی عبادات کی سردار عبادت نماز اور زکوٰۃ کو چُن لیا.اور اس کا ذکر بنی نوع انسان سے حسن سلوک کے بعد اس لئے کیا کہ بنی نوع انسان کے ساتھ حسن سلوک روحانیت کی طرف پہلا قدم ہے اور انسان کو کئی مواقع پر فطرتاً بغیر کسی شریعت کے اس کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے اور عبادات کا تفصیلی طور پر بجا لانا ایک دوسرا قدم ہے.پس جو شخص پہلا قدم اٹھائے گا.وہی دوسرا قدم اُٹھا سکے گا.یہ امر یادر کھنا چاہیے کہ قرآن کریم کبھی تو درجات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا پہلے ذکر کر دیتا ہے اور بندوں کے حقوق کا بعد میں ذکر کرتا ہے.اور کبھی بندوں کے حقوق کا پہلے ذکر کردیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بعد
Page 254
میں رکھتا ہے.درجہ کے لحاظ سے چونکہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے اور انسان ادنیٰ.اس لئے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ذکر پہلے رکھا جاتا ہے.اور بندوں کے حقوق کو بعد میں.مگر جہاں بندوں کے حقوق کا ذکر پہلے ہوتا ہے وہاں ان کی کمزوری کو مدنظر رکھ کر پہلے ذکر کیا جاتا ہے.اور چونکہ اللہ تعالیٰ کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہے اس لئے اس کے حقوق کا بعد میں ذکر کیا جاتا ہے.جیسے اِسی آیت میں یتامیٰ کی کمزوری کے لحاظ سے ان کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اور مساکین کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے.لیکن اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا ہے اور بعد میں بندوں کا حق بیان کیا ہے.اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ میں استقلال کے ساتھ بغیر کسی ناغہ کے نماز ادا کرنا شامل ہے.اور نوافل اس کے تابع ہیں اور اٰتُوا الزَّكٰوةَ میںصدقہ و خیرات بھی شامل ہیں.جو زکوٰۃ کے تابع ہے.گویا بدنی اور مالی دونوں قسم کی عبادات کی ادائیگی کا اس آیت میں ذکر فرما دیا.بہرحال قرآن کریم نے بائیبل کے پراگندہ احکام کو ایسی عجیب ترتیب دی ہے کہ جس سے ان احکام کی عظمت اور بھی نمایاں ہو گئی ہے.اوّل خدا تعالیٰ کی عبادت کو لیا کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے.پھر بندوں سے حسن ِ سلوک کا ذکرکیا.اور اُن میں سے بھی پہلے والدین کا ذکر کیا جو بطور حق کے حسنِ سلوک کے مستحق ہوتے ہیں.پھر قریبیوں اور رشتہ داروں کو رکھا.جن کا مقام والدین کے بعد دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے.اس کے بعد عام لوگوں کو لیا.اور اُن میں سے پہلے اُن کا ذکر کیاجو اپنی خبر گیری آپ کرنے کے قابل نہیں ہوتے یعنی یتامیٰ.پھر مساکین کو لیا جو بوجہ خود طاقت رکھنے کے اسقدر مدد کے محتاج نہیں ہوتے جس قدر کہ یتامیٰ.اِس کے بعد قُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا فرما کر سب لوگوں سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا.جس میں دو۲ امور شامل تھے.اوّل تمام بنی نوع انسان سے مذہب و ملّت کے امتیاز کے بغیر حسن سلوک.دوم بنی نوع انسان کی ترقی کی فکر اور دوسرے لوگوں کو اس کی تلقین.پھر یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تم خدا اور اس کی مخلوق دونوں کے حقوق توڑتے ہو اور ان احکام کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ تم ان کو تسلیم کرتے ہو تو یہ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ تم اِن حالات میں مومن ہو.اور وہ قوم جو دنیا کی اصلاح کر رہی ہے کافر ہے؟حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیںرہا.اور تم صداقت سے بہت دُور جا چکے ہو.اس جگہ اس سوال پر روشنی ڈالنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّہَ کہنے کی بجائے لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَکیوں فرمایا ہے.اگر لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّہَ کہاجاتا تو اس کے معنے یہ ہوتے کہ تم نے خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش نہیں کرنی.مگر کہا یہ گیا ہے کہ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ یعنی ہم نے انہیں کہاکہ تم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کی پرستش نہیں کروگے.گویا بجائے نہی پر زور دینے کے اُن سے اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے سوا
Page 255
اور کسی کے سامنے سر بسجود نہیں ہوںگے.پس طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں خدا تعالیٰ نےیہ نرالا طریق کیوں اختیار کیا ہے.سو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم اور عام عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ بعض دفعہ نہی پر زور دینے کے لئے نہی کی بجائے نفی استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بات زیادہ زوردار طریق پر ذہن نشین کروائی جا سکے.اس کی مثال ہماری زبان میں بھی پائی جاتی ہے.ہم بعض دفعہ ایک بچہ کو بجائے یہ کہنے کے کہ تم ایسا مت کرو یہ کہتے ہیں کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے.یا کہتے ہیں کہ میں تو یہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ تم ایسا کروگے.اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ طریق نہی سے زیاد ہ مؤثر ہے.یہی طریق اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اختیار فرمایا ہے.اور لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَکہنے کی بجائے لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ فرماکر اپنے اس یقین اور اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ تمہارے متعلق تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم شرک کروگے.بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہمیشہ اُسی کی عبادت کیا کرو گے.گویا یہ کام صرف بُرا ہی نہیں بلکہ ایک اور وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اس سے بچنا چاہیے.اور وہ ہمارے اور تمہارے تعلقات ہیں.ہم اُمید رکھتے ہیں کہ تم ان تعلقات کی وجہ سے ایسا کبھی نہیں کرو گے.یہ جذبات کو اُبھارنے کے لئے ایک نہایت ہی مؤثر طریق کلام ہے.اس سے جذباتِ محبت برانگیختہ ہو جاتے ہیں.اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شخص ایسے حکم کو توڑے تو اس کا جرم زیادہ شدید ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک حکم کو بھی توڑتا ہے اور دوسرے کی امید بھی ٹھکرا دیتا ہے.اِس کی اور توجیہات بھی کی گئی ہیں.مگر میرے نزدیک جذباتی پہلو کے لحاظ سے اس توجیہہ کو دوسری توجیہات پر فضیلت حاصل ہے.اس کی ایک توجیہہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ اصل میں یہ عَلٰی اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا ہے.حرف جار کو حذف کر دیا گیا ہےاور اس کے بعد اَنْ کو بھی محذوف کر کے فعل کو مرفوع بنا کر لَا تَعْبُدُوْنَ کر دیاگیا ہے.اور گو یہ بھی ممکن ہے.مگر میرے نزدیک پہلے معنے زیادہ اچھے ہیں.کیا بلحاظ معنوی خوبی کے اور کیا بلحاظ ظاہری کے.نفی اُمید بھی دلاتی ہے اور اس میں نہی بھی آجاتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ان توقعات کا اظہار کیا تھا کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائو گے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کروگے، یتامیٰ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کروگے اور لوگوں کو ہمیشہ اچھی باتیں کہو گے.نمازیں پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے اور یہ وہ احکام ہیں جن سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق تمہیں اختلاف ہے.حضرت مسیحؑ ناصری کی صداقت کے متعلق تمہیں اختلاف ہے مگر یہ ایسی باتیں ہیں جن سے تمہیں کوئی اختلاف نہیں بلکہ تم خود ان کو اپنے لئے تسلیم کرتے ہو.تمہیں کہا گیا تھا کہ تم توحید الہٰی پر قائم رہو اور تم اس بات کو مانتے ہو کہ تمہیں ایسا حکم دیا گیا تھا.تمہیں
Page 256
کہا گیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو.اور تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہیں واقع میں یہ تعلیم دی گئی تھی.تمہیں رشتہ داروں، یتامیٰ اور مساکین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا گیا تھا.اور تم مانتے ہو کہ یہ بات درست ہے.پھر تمہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ دو.ان کے جذبات کا خیال رکھو.اُن کے ساتھ اچھی طرح پیش آئو.اور تم یہ اقرار کرتے ہو کہ ہمیں یہ احکام دیئے گئے تھے.پس سوال یہ ہے کہ کیا تم ان احکام پر عمل کرتے ہو.اگر تم اپنے حالات کا جائزہ لو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم ان احکام پر عمل نہیں کرتے.اس میں کوئی شُبہ نہیں کہ ہر قوم میں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام خرابی واقع ہونے کے بعد بھی نیکی پر قائم رہتے ہیں مگر وہ قوم بحیثیت مجموعی مرُدہ ہی کہلاتی ہے کیونکہ اس کی اکثریت احکامِ الہٰی سے اعراض کر رہی ہوتی ہے اور یہی یہود کی کیفیت تھی.یہاں یہ شُبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے یہود نے صرف ظاہری طور پر کسی مجبوری یا ناواقفیت کی وجہ سے ایسا کیا ہو.ورنہ دلوں میں وہ ان احکام کی عظمت اور ان کی اہمیت کے قائل ہوں.جیسے مسلمانوں میں کئی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے.کئی ہیں جو روزے نہیں رکھتے.کئی ہیںجو زکوٰۃ نہیں دیتے.کئی ہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے.مگر وہ اپنے دلوں میں نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں.اور اپنی بدعملی کو صرف غفلت اور گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں.اِسی طرح ممکن ہے یہود بھی صرف ظاہری طور پر بد عمل ہو چکے ہوں اور دلوں میں ان احکام کی عظمت کے قائل ہوں.اس شُبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَکے الفاظ استعمال فرمائے ہیں.ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْمیں تو اس طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارا ان احکام پر ظاہری طور پر کوئی عمل نہیں.اور اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ تمہارے دلوں میں بھی ان کی طرف کوئی رغبت نہیں رہی.اور اب تم موسوی شریعت سے کلی طور پر بیگانہ ہو چکے ہو.گویا ظاہری طور پر بھی تم میں بے دینی اور اباحت پیدا ہو گئی ہے اور باطنی طور پر بھی تمہاری روحانیت مر چکی ہے.وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَ لَا اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم (آپس میں ) اپنے خون نہ بہاؤگے اور اپنے آپ کو تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ (یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو) اپنے گھروں سے نہ نکالو گے اور تم نے (اس کا) اقرار کر لیا تھا اور تم
Page 257
تَشْهَدُوْنَ۰۰۸۵ (اس عہد کے متعلق ہمیشہ )گواہی دیتے رہے ہو.تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کے دو اور تمدنی نقائص بیان کرتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان میں خاص طور پر پائے جاتے تھے.اورجن کے وہ اکثر مرتکب ہو ا کرتے تھے.فرماتا ہے کہ تم اس وقت کو بھی یاد کرو.جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے خون نہ بہائو گئے اور اپنے آپ کو اپنے گھر وں سے نہ نکالو گے.اپنے خون بہانے سے اس جگہ اپنے ہم قوموں کا قتل مراد ہے.اور یہ الفاظ اس لئے اختیار کئے گئے ہیں کہ اپنی قوم کو قتل کرنا درحقیقت اپنا ہی قتل کرنا ہوتا ہے.کیونکہ بعض افرادکی ہلاکت یا ان کا قتل تمام قوم پر بحیثیت مجموعی اثر انداز ہوتا ہے.اِسی طرح اپنے آپ کو گھروں سے نکال دینے سے بھی اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا مراد نہیں.جیسا کہ خود اگلی آیت سے ظاہر ہوتا ہے بلکہ اس سے مراد بھی اپنی قوم کا نکالنا ہے.ورنہ کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکالا نہیں کرتا.اس جگہ بھی پچھلی بیان کردہ حکمت کے ماتحت قوم کے بعض افراد کے نکالنے کا ذکر کرنے کی بجائے اپنا نکالنا بیان کیا گیا ہے تاکہ ان کو اپنی حماقت کا احساس ہو.مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور اپنی قوم کے افراد کو اپنے گھروں سے نکالنا تمہارے لئے ممنوع قرار دیا گیا تھا.مگر تم نے اس حکم کو بھی توڑا جیسا کہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے.اِس آیت کے شروع میں الفاظ وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ رکھے گئے ہیں.اور اس سے پہلی آیت کو وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ سے شروع کیا گیا ہے.حالانکہ دونوں عہد بنی اسرائیل سے ہی لئے گئے تھے.پھر ان دو آیتوں میں مختلف الفاظ کیوں رکھے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ ایک عجیب کمال ہے جو اس کے بے نظیرہونے کے ہزاروں دلائل میں سے ایک دلیل ہے.کہ وہ الفاظ کی خفیف تبدیلیوں سے مختلف مضامین ادا کر جاتاہے اور فقروں کا کام لفظوں سے لے لیتا ہے.اس جگہ بھی بنی اسرائیل کی جگہ کُمْ رکھ کر ایک خاص امر کی طرف متوجہ کیا ہے اور وہ یہ کہ اول الذکر بدیاں تو وہ تھیں جو اس وقت تمام بنی اسرائیل میں پھیلی ہوئی تھیں.اور مؤخر الذکر بدیاں وہ ہیں جو خاص طور پر یہود کے اُن قبائل میں رائج تھیں جو مدینہ اور اس کے نواح میں رہتے تھے.پس ایک جگہ بنی اسرائیل کا لفظ رکھ کر اس کی عمومیت کی طرف اشارہ کیا تو دوسری طرف کُـمْ فرما کر عرب کے یہودقبائل کو
Page 258
خاص طور پر مخاطب کیا اور انہیں اس طرف توجہ دلائی کہ ان بدیوں کے تم خاص طور پر شکار ہو.ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ.اس میں بتایا کہ بعض اوقات محض ادب کی وجہ سے انسان کسی بات کو مان لیتا ہے مگر اس کا دل اس کی برتری اور اہمیت کا قائل نہیں ہوتا.لیکن ہمارے یہ احکام اتنے اعلیٰ درجہ کے تھے کہ نہ صرف تم نے اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کیا بلکہ تمہارے دل بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ احکام بہت مفید ہیں.مگر تم نے اپنے اقرار کو بھی پسِ پُشت پھینک دیا اور اپنی قلبی شہادت کو بھی ٹھکرا دیا.اور اپنے بھائیوں کے خلاف تم نے جنگ شروع کر دی.ثُمَّ اَنْتُمْهٰؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا پھر تم لوگ ہی ہو کہ(اس عہد کے باوجود) آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ١ٞ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ جماعت کو گناہ اور ظلم کے ساتھ (ان کے دشمنوں کی ) مدد کرتے ہوئے ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور اگر وہ وَ الْعُدْوَانِ١ؕ وَ اِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ تمہارےپاس قیدی ہو کر (مدد مانگنے کے لئے) آئیں.تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑالیتے ہو گو حقیقتاً ان کا (گھر وں عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ١ؕ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَ سے) نکالنا (بھی) تم پر حرام کیا گیا تھا.تو کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصہ کا انکار کرتے ہو ؟ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ١ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا پس تم میں سے جو ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس (جہان کی) زندگی(ہی) میں رسوائی(اٹھانے )کے سوا اور کیا ہے خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا١ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى (جو انہیں ملے گی )اور وہ قیامت کے دن اس سے بھی سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور
Page 259
اَشَدِّ الْعَذَابِ١ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۰۰۸۶ جو کچھ تم کر رہے ہواللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں.حَلّ لُغَات.خِزْیٌ.یہ لفظ.ذلّت ،سزا،بُعد اور ندامت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.چنانچہ لُغت میں لکھا ہے.اَلخِزْیُ: اَلْھَوَانُ وَالْعِقَابُ وَالْبُعْدُ وَالنَّدَامَۃُ.(اقرب الموارد) تفسیر.اس آیت میں بتایا کہ یہود کی یہ کیفیت ہے کہ باوجود اس کے کہ شریعت میں ان کو ان دونوں کاموں سے روکا گیا تھا.پھر بھی وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں.گھروں سے نکالنے کا مطلب یا تو جلاوطن کرنا ہوتا ہے یا دوسرے کو غلام بنا لینا.غلام چونکہ دوسرے کے تابع ہوتا ہے اور وہ اُسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے.اس لئے اس جگہ گھروں سے نکالنے کے معنے جلاوطنی کے نہیں بلکہ غلامی کے ہیں.بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ اس سے پہلے سَفْکُ الدِّمَآءِ کا ذکر کیا گیا ہے.جس میں جنگ کی طرف اشارہ ہے.پس ضروری ہے کہ گھروں سے نکالنے کے معنے غلامی ہی کے لئے جائیں جو جنگ کے نتیجہ میں لازماً پیدا ہوتی ہے.یہ حکم کہ تم دوسروں کو قتل نہ کرو.خروج باب۲۰ آیت ۱۳ میں اس طرح آتا ہے کہ ’’ ُتو خون مت کر.‘‘ اور دوسروں کو گھروں سے نہ نکالنے کا اصولی ذکر خروج باب ۲۱ آیت ۱۶ میں پایا جاتا ہے.وہاں لکھا ہے.’’ اور جو کوئی کسی آدمی کو چُرائے خواہ وہ اُسے بیچ ڈالے خواہ وہ اس کے ہاں ملے.وہ قطعی مار ڈالا جائے.‘‘ اِسی طرح کسی اسرائیلی کو غلام بنانے کی ممانعت کا ذکر احبار باب ۲۵ آیت ۳۹ تا ۴۱ میں اس طرح کیا گیا ہے کہ ’’اگر تیرا بھائی جو تجھ پاس ہے مفلس ہو جائے اور تیرے ہاتھ بک جائے تو تُو اس سے غلام کی مانند خدمت نہ کروا بلکہ وہ مزدور اور مسافر کی مانند تیرے ساتھ رہے اور یوبل کے سال تک تیری خدمت کرے.اور بعد اس کے وہ تجھ سے جُدا ہو جائے گا.اور وہ اور اس کے لڑکے اُس کے ساتھ اور اپنے گھرانے کے پاس اور اپنے باپ کی ملکیت کو پھر جائے گا.‘‘ اِسی طرح احبارباب۲۵ آیت ۵۴ میں لکھا ہے.
Page 260
’’اگر وہ اِن برسوں میں چھڑا یا نہ جائے تو یوبل کے سال میں(جو ہر ساتویں سال آتا ہے) وہ آزاد ہو جائیگا.اور اس کے لڑکے اس کے ساتھ.‘‘ اِن احکام سے یہود نے جو کچھ نتیجہ نکالا وہ نحمیاہ نبی کے طریق عمل سے ظاہر ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کے سب غلاموں کو آزاد کروادیا.ان کو بھی جو غیر قوموں کے پاس تھے اور ان کو بھی جو اپنوں کے پاس تھے.( نحمیاہ باب ۵ آیت۸) اور طالمودک زمانہ میں تو یہود کا اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ یہودی غلام نہیں بنایا جا سکتا.چنانچہ انسائیکلوپیڈیا ببلیکا جلد ۴ میں لکھا ہے.’’یہ اصل کہ کوئی یہودی کبھی غلام نہیں بنایا جا سکتا طالمودی قانون میں شامل کیا گیا.حتّٰی کہ وہ چو ر بھی جسے اُس کے جرم کی وجہ سے فروخت کیا جاتا تھا.غلام نہیں سمجھا جاتا تھا.اور سلوقیوں SCLEUCIDS اور ٹولمیوںPTOLEMIESکی جنگ کے وقت جب بہت سے یہودی کافروں کے ہاتھ میں قید ہو گئے تو ان کا چھڑانا ایک فرض اور ثواب کا کام سمجھا جاتا تھا.‘‘ (انسائیکلوپیڈیا ببلیکا زیر لفظ Slavery) اِن احکام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو غلام بنانا جو اُن کو گھروں سے نکالنے کے مترادف ہے بائیبل کے حکم کے مطابق ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا.اور اگر کوئی قید ہو جائے تو اس کے لئے ایسے احکام تھے جن کے نتیجہ میں وہ جلد سے جلد آزاد ہو جائے.یہودی غلام صرف دو طرح بن سکتاتھا.اوّل اس طرح کہ کوئی اپنے آپ کو بیچ ڈالے.ہماری شریعت نے اسے ناجائز قرار دیا ہے مگر اُن میں یہ جائز تھا.وہ قرضہ اور تنگی کے باعث اپنے آپ کو فروخت کر سکتے تھے.دوم اس طرح کہ عدالت ان کو بیچ دے.خواہ قرضہ میں بیچے یا کسی ایسے جرم کے نتیجہ میں بیچے جس سے مالی طور پر دوسرے کا نقصان ہوا ہو.مثلاً کسی نے چوری کر لی ہو یا غبن کر لیا ہو یا کوئی اور نقصان پہنچایا ہو.مگر اِن دونوں صورتوں میں غیر یہودی کے ہاتھ میں اس کا غلام ہونا بہت ہی بُرا سمجھا جاتا تھا.حتیّٰ کہ عدالت جس کو بیچتی تھی اس کو بھی کسی غیر یہودی کے ہاتھ نہیں بیچ سکتی تھی.اِس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باوجود اس کے کہ تم کو یہ احکام دیئے گئے تھے تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو.یعنی اس سے جنگ کرتے ہو.اور تم میں سے ایک فریق اپنے آدمیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتا ہے.یعنی اس جنگ کے نتیجہ میں وہ قید ہو کر غلام بنا لئے جاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کی گناہ اور ظلم
Page 261
سے مدد کرتے ہو.حالانکہ شرعاً تمہارے لئے ان کے خلاف ایسا قدم اٹھانا جائز ہی نہیں.اور اگر وہ قیدی کی صورت میں تمہارے پاس لائے جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو.حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا.یعنی پہلا کام جس کے نتیجہ میں تم فدیہ دے کرانہیں چھڑاتے ہو وہ بھی تم پرحرام تھا مگر تم نے اس کا ارتکاب کر لیا.اس کے معنے یہ ہیں کہ تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو.اللہ تعالیٰ نے اس جگہ یہود کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جن کا وہ مدینہ کے مشرک قبائل کے ساتھ مل کر ارتکاب کیا کرتے تھے.اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے قبل مشرکوں کی دو پارٹیاں تھیں.جن میں سے ایک کا نام اَوس اوردوسری کا نام خزرج تھا.بعثت سے کچھ عرصہ پہلے سے ان کی آپس میں جنگ چلی آتی تھی.یہودی قبائل جو مدینہ میں اس خیال سے آکر آباد ہو گئے تھے کہ جب وہ موعود نبی جو اس ملک میں آنے والا ہے آئے گا تو ہم اُس پر ایمان لائیں گے.وہ تین تھے.بنو قریظہ،بنو قینقاع اور بنو نضیر.اُس زمانہ کے دستور کے مطابق جَتھہ بندی ہی امن کا ذریعہ تھی.اس کے بغیر لوگ اطمینان سے نہیں رہ سکتے تھے چونکہ اَوس اور خزرج کی آپس میں جنگ تھی اس لئے انہوں نے یہودی قبائل سے سمجھوتہ شروع کر دیا.بنو قینقاع اور بنو قریظہ اَوس کے حلیف ہو گئے اور بنو نضیر خزرج کے ساتھ مل گئے.جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو یہودی بھی اپنے معاہدہ کے مطابق اُن کے ساتھ جنگ میں شامل ہوتے اور اُن کے ساتھ ہو کر لڑتے اور ان کی مدد کرتے.اس طرح ہر قبیلہ اپنے عمل سے دوسرے یہودی قبیلہ کو جنگ کے لئے اُس کے گھر سے نکالتا.لیکن جنگ کے بعد ان میں سے جو پارٹی بھی جیتتی وہ جہاں دوسرے قبیلہ کے آدمیوں کو قید کرتی وہاں یہودیوں کو بھی قید کر لیتی.اس پر اُس پارٹی کے یہودی جو ہار جاتی تھی اُن سے جا کر کہتے کہ ہمارے مذہب میں یہودی کو غلام بنانا ناجائز ہے اس لئے تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو.چنانچہ وہ آپس میں چندہ کر کے ایک بڑی رقم بطو ر فدیہ اُن کو دیدیتے اور یہود کو مشرکین کی غلامی سے آزاد کروالیتے اور کہتے کہ یہودی کا کسی غیر یہودی کے پاس غلام رہنا درست نہیں.(السیرۃ النبی لابن ہشام )اللہ تعالیٰ یہود کے اس فعل کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم کو دو باتوں سے منع کیا گیا تھا.آپس میں جنگ کرنے سے بھی اور اپنے بھائیوں کو غلام بنانے سے بھی.مگر تم جنگ بھی کرتے ہو اور اُس کے نتیجہ میں اپنی قوم کے افراد کو غیر یہودیوں کا غلام بنانے یا بنوانے کی کوشش بھی کرتے ہو.مگر غلام بنواتے وقت توتمہیں یہ خیال نہیںآتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.اور جب وہ غلام بن جاتے ہیں تو تم بڑے نیک بن کر انہیں فدیہ دے کر چھڑالیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ نے یہود
Page 262
کو غلام بنانا حرام کیا ہوا ہے.حالانکہ تم خود غیر یہودیوں کی مدد کر کے آپس میں جنگ کرتے ہو اور یہودیوںکو اُن کے ہاتھوں میں قید کرواتے اور اُن کو غلام بناتے ہو.پس اِس سے زیادہ اور کیا شرارت ہو گی کہ تم ایک حصہ کتاب کو تو مانتے ہو اور ایک کو ردّ کرتے ہو.ایک طرف یہودی غلاموں کو آزاد کرواتے ہو اوردوسری طرف خود ایسے اسباب پیدا کرتے ہو جن سے وہ غلام بنیں.پھر تمہارا آپس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں.تم صرف ایک مشرک قبیلہ کی دوستی کی وجہ سے لڑتے ہو اور اپنے آدمیوں کو غیر مذاہب والوں کا غلام بنا کر کہتے ہو کہ ان کو چھڑانا چاہیے.تاریخ میں لکھا ہے کہ جب عرب کے قبائل یہودیوں کو طعنہ دیتے کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ خود پہلے جنگ کرتے ہو اور پھر فدیہ دے کر اور یہ کہہ کر کہ ہم میں یہود کا غلام بنانا ناجائز ہے ان کو چھڑاتے ہو تو وہ کہتے کہ ہمارے لئے ان سے لڑنا تو منع ہے لیکن ہمیں اپنے حلیفوں سے شرم آ جاتی ہے اور مجبوراً لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں اس لئے بعد میں فدیہ دے دیتے ہیں.(محیط زیر آیت ھذا) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو.یعنی جو شخص ایک حصہ کتاب کو مانتا ہے وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اس کتاب کی صداقت کا قائل ہے.پس اس کا دوسرے حصے کو ترک کرنا اس کے نفس کی گندگی پر دلالت کرتا ہے.فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا١ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ.فرماتا ہے کہ تمہارے جیسے لوگ جن کو اصلاح کے اِس قدر مواقع دیئے گئے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کی باتوں سے اِس قدر واقف ہیں تمہیں سوائے اس کے اور کیا سزا دی جا سکتی ہے کہ ان جرائم کی وجہ سے تمہیں دنیا میں رسوا کر دیا جائے اور آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا.حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی مرض جو انسان کی رُوح کو کھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے منشا اپنے خیالات اور اپنی آرزو کے مطابق مذہب کی جس بات کو دیکھتے ہیں صرف اُس پر عمل کرنا وہ اپنے لئے کافی سمجھ لیتے ہیں اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے کہ کئی اور احکام بھی ہیں جن کو وہ بڑی دلیری سے نظر انداز کر رہے ہیں.چونکہ بنی نوع انسان کی عادات مختلف حالات اور مختلف صحبتوں کی وجہ سے بدلتی رہتی ہیں.اس لئے ہر انسان اپنا ایک خاص ذوق رکھتا ہے جس کو وہ پورا کر لیتا ہے.اور جو چیز اس کے ذوق کے خلاف ہو اُسے نظر انداز کر دیتا ہے.اگر اپنے ملک کے مختلف علاقوں پر ہی نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہو گا کہ بعض مقامات کے لوگ نمازوں کے زیادہ پابند ہوتے ہیں اور روزوں میں سُستی کرتے ہیں.بعض جگہ کے لوگ زکوٰۃ تو بڑی پابندی سے دیتے ہیں مگر نماز اور روزہ کی پروا نہیں کرتے.اِسی طرح بعض جگہ نماز اور روزہ کی تو پابندی کی جاتی ہے مگر زکوٰۃ کی طرف توجہ
Page 264
پسِ پُشت ڈالدیا ایسے لوگوں کو ہم ذلیل اور رُسوا کریں گے کیونکہ یہ لوگ جب اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے احکام کی پروا نہیں کرتے اور جب اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہیں تو مان لیتے ہیں.حالانکہ سچا مومن وہ ہے جو ہر بات میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مدنظر رکھے.حضرت خلیفۃ المسیح اوّل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص جو زانی تھا میں نے اس کو نصیحت کی کہ یہ کام چھوڑ دو.وہ کہنے لگا.میں نے تو فلاں عورت سے عہد کیا ہوا ہے کہ تم سے بیوفائی نہیں کروں گا.اگر آپ فرماتے ہیں تو میں بیوفائی کا جرم کر لیتا ہوں.گویا اُس شخص نے بے وفائی اور عہد کے توڑنے کو تو گناہ سمجھا لیکن زنا کے متعلق کسی گناہ کا خیال نہ آیا.پس مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت ہوشیار رہے اور یہود کی طرح خدا تعالیٰ کے احکام کے ساتھ یہ تمسخر نہ کرے کہ جس حکم پر جی چاہا عمل کر لیا اور جس کے متعلق جی چاہا اُسے نظر انداز کر دیا.چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ ایک زمانہ میں مسلمان بھی یہود کے نقش قدم پر چلیں گے اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے.(بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ باب قول النبی لا تتبعن سنن من کان قبلکم) اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام پر تنزل کا دور آیا تو وہ تمام خرابیاں جو یہود میں پائی جاتی تھیںایک ایک کر کے مسلمانوں میں بھی پیدا ہونے لگ گئیں.یہود کو کہا گیا تھا کہ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ دیکھواپنی قوم کے افراد سے مت لڑو.اور اُن کا خون مت بہائو.ورنہ تم کمزور ہو جائو گے.اور یہی نصیحت مسلمانوں کو بھی کی گئی تھی.مگر اسلام کے دَورِ تنزل کی تاریخ اس بات پر شاہدہے کہ مسلمانوں نے خود مسلمانوں کا خون بہایا.اور اپنی حکومتوں کو تباہ کرنے کے لئے انہوں نے ہر قسم کی خفیہ ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے کام لیا یہاں تک کہ عیسائی حکومتوں سے معاہدہ کر کے مسلمان حکومتوں کا تختہ اُلٹنے کی بھی شازشیں کیں.چنانچہ خلافتِ اندلس نے روما کے عیسائی بادشاہ سے خفیہ معاہدہ کیا کہ وہ اُس کے ساتھ مل کر خلافتِ عباسیہ کو تباہ کرے گی اور عباسی حکومت نے شاہِ فرانس سے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ وہ سپین کی اسلامی حکومت کو متزلزل کرنے کے لئے اس کا ساتھ دے گی.گویا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے بھائیوں کے خون سے رنگے.اور یہ نہ سمجھا کہ اسلامی سیاست میں مسیحیوں کو داخل کر کے وہ اسلام کو کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں.اسی طرح صلاح الدین ایوبی جب سارے یورپ کے مقابلہ میں لڑ رہا تھا.اُس وقت مسلمان اور عیسائی حکومتوں نے باہم معاہدہ کر کے اس کو قتل کرنے کی سازش کی اور آخر ایک مسلمان کو ہی اس کام پر مقرر کیا گیا اور اُس نے صلاح الدین پر نماز پڑھتے ہوئے قاتلانہ حملہ کر دیا گو اللہ تعالیٰ نے اُس پر فضل کیا اور وہ اس قاتلانہ حملہ سے محفوظ رہا.
Page 265
پھر یہود کو کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کیا دوغلی پالیسی اختیار کر رکھی ہے کہ ایک طرف اپنے بھائیوں سے جنگ کرتے ہو اور دوسری طرف جب وہ قید ہو جاتے ہیں تو تم فدیہ دے کر اُن کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہو.یہی کیفیت مسلمانوں کی بھی نظر آنے لگی.چنانچہ پہلی جنگ عظیم میں مسلمانوں نے ترکوں کے خلاف لشکروں میں بھرتی ہو کر جنگ کی.لیکن جب وہ لوگ قید ہو گئے تو پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑانا چاہا.غرض جس طریق پر یہود نے قدم مارا تھا مسلمانوں نے اسی طریق پر چلنا شروع کر دیا حالانکہ یہ واقعات اس لئے بتائے گئے تھے کہ مسلمان ہوشیار رہیں اور اپنے اندر ان خرابیوں کو پیدا نہ ہونے دیں.بیشک جہاں تک اہل کتاب کی اصلاح کا سوال ہے اِس سے یہود اور نصاریٰ ہی مراد ہیں.لیکن اس میں کیا شبہ ہے کہ مسلمان بھی اہل کتاب ہیں.بلکہ صحیح معنوں میں اہل کتاب صرف مسلمان ہی کہلا سکتے ہیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کامل کتاب عطا فرمائی ہے جبکہ دوسری قومیں ایسی کامل اور بے عیب کتاب سے محروم ہیں.پس اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ یہود اور نصاریٰ کی خرابیوں پر کڑی نگاہ رکھتے.اور ان کو اپنے اندر نہ آنے دیتے.اُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ١ٞ فَلَا اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس( جہان کی )زندگی کو بعد میں آنے والی (زندگی )پر مقدم کر لیا ہے.اس لئے نہ تو يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَؒ۰۰۸۷ ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی (کسی اور رنگ میں )مدد کی جائے گی.تفسیر.اِس آیت میں بتایا کہ چونکہ یہود نے دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کر لی ہے.اس لئے اِس جرم کی سزا میں اب ان سے دنیا کی حکومت چھین لی جائے گی.اور جب تک کہ وہ پھر دین کو اختیار نہ کریں اُس وقت تک اُن کے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی.فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَسے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ آسمانی عذاب بھی اُن سے کم نہیں ہوں گے اور دنیا کی قومیں بھی ان پر رحم نہیں کریںگی.قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے مضمون کو آخر میں پھر دُہرادیتا ہے.شروع میں بیان فرمایا تھا کہ یہود کا یہ خیال کہ ہمیں صرف چند دن عذاب ہو گا.غلط ہے.اب آخر میں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ فرما کر بتادیا کہ اس رکوع
Page 266
میں بھی لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً والا مضمون ہی چل رہا تھا جو یہاں آکر ختم ہوا.اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ تم شریعت کے احکام کو اس طرح کھیل بنا لینے کے جُرم میں مختلف قسم کے آسمانی عذابوں میں گرفتار رہو گے اور تمہیں کسی کی مدد حاصل نہیں ہو سکے گی.پس تمہارا یہ دعویٰ کہ تمہیں صرف چند دن عذاب ہو گا باطل ہے.تمہیں عذاب ہو گا اور عذاب بھی ایسا کہ جو ہلکا نہیں کیا جائے گا.یعنی ایک لمبے عرصہ تک وہ تمہیں سوزش اور جلن میں مبتلا رکھے گا.دوسرا خیال ان کا یہ تھا کہ ہمارا انبیاء سے تعلق ہے.وہ ہماری مدد کریں گے.سو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ ان کا یہ خیال بھی غلط ہے.ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا.غرض قرآنی ترتیب کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے پہلے مضمون کو آخر میں پھر دُہرا دیتا ہے اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں گزشتہ بحث ختم ہوتی ہے.اور آئندہ نیا مضمون شروع ہوتا ہے.اِس رکوع میں پہلے جس عہد کا ذکر کیا تھا وہ عام تھا مگر اس کے بعد اس خاص عہد کا ذکر کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اُن یہود سے تعلق رکھتا ہے جو مدینہ اور اس کے نواح میں رہنے والے تھے.اس کے بعد اُن کی دو۲ اور قومی غلطیوں کا ذکر فرمایا.یہ وہ غلطیاں تھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہود میں خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی تھیں.پھر اس ترتیب میں بھی پہلے ان غلطیوں کا ذکرکیاجو نیکیوں کے ترک کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں.اور پھر ان غلطیوں کا ذکر فرمایا جو اپنی ذات میں گناہ اور ظلم ہیں.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک وہ جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جن کا نوع انسان سے تعلق ہوتا ہے.پھر وہ گناہ بھی جن کا دوسروں سے تعلق ہوتا ہے.دو۲ قسم کے ہوتے ہیں.اوّل وہ گناہ جن میں انسان کو احساس ہو کہ میںگناہ کر رہا ہوں اور وہ اُن گناہوں کو چُھپانے کی کوشش کرے.دوم وہ گناہ جن کے کرتے وقت انسان محسوس ہی نہ کرے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں.اِس رکوع میں اللہتعالیٰ نے تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ فرما کر دو۲ مثالیں یہود کے اُن گناہوں کی بیان فرمائی ہیں جن کے متعلق انہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تو وہ ملامت کریں گے مگر باوجود اس کے کہ یہ نہایت واضح گناہ تھے اور ان کا اُن کی قوم کے ساتھ تعلق تھا پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ اِن گناہوں میں ملوث رہے اور اپنی شریعت کی بے حرمتی کرتے رہے.
Page 267
وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ١ٞ اور ہم نے( یقیناً) موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے بعد ہم نے (ان) رسولوں کو (جنہیں تم مانتے ہو) اس کے پیچھے وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ بھیجا.اور عیسیٰ ابن مریم کو (بھی)ہم نے کھلے کھلے نشانات دیئےاور روح القدس کے ذریعہ سے اسے طاقت بخشی الْقُدُسِ١ؕ اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰۤى (لیکن تم نے سب کا مقابلہ کیا )تو پھر( تم ہی بتاؤکہ)کیا (یہ بات ناپسندیدہ نہیں کہ) جب بھی تمہارے پاس کوئی اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ١ۚ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ١ٞ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ۰۰۸۸ رسول اس (تعلیم )کو لے کرآیاجسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر (کا مظاہرہ) کیا.چنانچہ بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا.حَلّ لُغَات.قَفَّیْنَا: قَفٰی فُـلَانٌ زَیْدًا اَوْ بِزَیْدٍ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنے ہیں وہ زید کے پیچھے پیچھے چلا.اور قَفّٰی کے معنے ہیں پیچھے چلایا.یہ لفظ قَفَاسے نکلا ہے اور قَفَا انسان کے سر کا پچھلا حصہ ہوتا ہے جسے اردو زبان میںگُدی کہتے ہیں.اورگُدی کے ساتھ ساتھ ہونے کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ وہ چیز پیچھے بھی ہو.اور قریب بھی.اصل معنے تو اس کے ساتھ ساتھ اور قریب قریب جانے کے ہیں مگر محاورہ میں اس کے معنے وسیع کر لئے گئے ہیں.اس لئے اب یہ لفظ ایسے موقع پر بھی استعمال کر لیا جاتا ہے جبکہ کوئی پیچھے چل کر آئے خواہ وہ فاصلہ پر ہی ہو.(اقرب) بَیِّنٰت.وہ دلائل ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں.دلائل دو۲ قسم کے ہوتے ہیں.اوّل وہ جن سے کسی نبی کی صداقت کا استنباط کیا جاتا ہے.مثلاً زمانہ کے خراب ہوجانے کے وقت نبوت اور اس کی ضرورت بتانے کے لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا خراب ہو گئی ہے.لوگ شریعت کو بھول گئے ہیں.اس کے احکام انہوں نے ترک کر دیئے ہیں اس لئے اب ایک نبی کی ضرورت ہے اور وہ آنے والا یہی ہے.یہ سب باتیں ایک نبی کی ضرورت بتانے کے لئے بطور استنباط ہوتی ہیں.یہ دلائل تو ہیں مگر بیّنات نہیں کہلا سکتے.اسی طرح اگر کوئی
Page 268
ایسی پیشگوئیاں ہوں جو قرب زمانہ کی تعیین کرتی ہوں نہ کہ خود اس زمانہ کی تو وہ پیشگوئیاں بھی اُس نبی کے لئے بیّنات میں سے شما ر نہیں ہوں گی.جیسے وہ نشانات و حالات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ظاہر ہو ئے.اور جن سے آپ کی صداقت کا استنباط کیا جا سکتا ہے وہ آپ کی صداقت کے دلائل تو ہیں مگر چونکہ وہ معیّن رنگ میں آپ کی شناخت نہیں کراتے اس لئے وہ بینات نہیں کہلا سکتے ہیں.مگر دوسری قسم کے دلائل وہ ہیں جو بیّنات کہلاتے ہیں.وہ ایسے دلائل ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں کسی نبی کی صداقت کا مشاہدہ کراتے ہیں.اور جن کے ذریعہ حق و باطل بالکل کھل جاتا ہے.جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصَّلوٰۃ وَالسَّلام نے بھی طاعون کی پیشگوئی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاعون کی پیشگوئی فرمائی.اب یہ صرف دلیل ہی نہیں بلکہ بیّنہ بھی ہے.کیونکہ یہ پیشگوئی صرف یہی ثابت نہیں کرتی کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آنیوالے کو آنا چاہیے بلکہ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں.غرض بیّنہ وہ ہوتی ہے جو صداقت کی وضاحت کر دیتی ہے.مگر دوسری دلیل صرف اشارہ کنا یہ سے صداقت کی طرف راہنمائی کرتی ہے.حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کے بعض دلائل صرف کنایہ و اشارہ کی قسم میں سے ہیں اور بعض بیّنات ہیں.اور درحقیقت ہر نبی دونوں قسم کے دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے.کیونکہ صرف کنایہ و اشارہ ہی صداقت کے ثبوت کے لئے کافی نہیں ہو سکتا.بلکہ اس کے ساتھ بیّنات کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ عام لوگوں پر اس کی صداقت واضح ہو جائے ورنہ ان کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا انتظار کیا جار ہا تھا.اَلْبَیّنَاتُ کے معنے علّامہ ابوحیّان اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں اَلْحُجَجُ الْوَاضِحَۃُ الدَّالَّۃُ عَلٰی نُبُوَّتِہٖ.یعنی ایسے واضح دلائل جو حضرت مسیح ؑ کی نبوت کو ثابت کرنے والے تھے(بحر محیط زیر آیت ھذا) رُوْحُ الْقُدُ سِ کے معنے لسان العرب میں یہ لکھے ہیں کہ خدا کا پاک یا مبارک کلام.رُوح کے معنے کلام اور قُدس کے معنے مبارک یا پاک کے ہیں.اس لئے دونوں لفظوں کے مل کر یہ معنے ہوئے کہ مبارک یا مقدس کلام.لسان العرب اور عربی کی دوسری لغت کی کتب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیس کا لفظ صرف اُن اشیاء کے متعلق بولا جاتا ہے جو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہوں یوں تو پاکیزگی کے لئے اور بھی کئی الفاظ ہیں مگر ان کے لئے یہ شرط نہیں.صرف تقدیس کے متعلق یہ شرط ہے کہ اس کا استعمال شرعی یا روحانی اشیاء کے متعلق ہوتا ہے.پس مقدس پاکیزگی وہ ہے جو شریعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہو.جیسے مقدس مقام وہ ہو گا جو شرعی اور روحانی طور پر اعزاز رکھتا ہو.یوں تو نظافت کا لفظ بھی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے.مگر اس کا تعلق شرعی اور روحانی پاکیزگی کے ساتھ نہیں ہوتا.جیسے ایک کافر بھی نظیف کہلا سکتا ہے لیکن مقدس انسان وہی کہلاسکتا ہے جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانی اعزاز حاصل
Page 269
ہو.اِسی طرح مبارک اور مقدس کلام بھی صرف پاکیزہ خیالات کو ہی نہیں کہتے ورنہ ایک فلاسفر کے خیالات بھی پاکیزہ ہو سکتے ہیں.وہ بھی طبیعات کے متعلق نئے سے نئے نکتے نکالتا رہتا ہے.مگر وہ مؤید بروح القدس نہیں ہوتا.وہ وحی الٰہی سے مشرف نہیں ہوتا.وہ ایسے خیالات سے مشرف نہیں ہوتا جو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر دیتے ہیں.مؤید بروح القدس صرف وہ کلام ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو.اور جو ہر لحاظ سے مبارک اور پاکیزہ ہوتا ہے.(۲) رُوح کے معنے فرشتہ کے بھی ہوتے ہیں.اس لحاظ سے روح القدس کے معنے ہیں فرشتۂ تقدس و برکات.فرشتے دو۲ قسم کے ہوتے ہیں.اوّل وہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام لاتے ہیں.دومؔ وہ جو اس کلام کو یا قضاء وقدر کو دنیا میں جاری کرتے ہیں.جو فرشتے کلامِ الٰہی لانے والے ہوتے ہیں اُن کو روح القدس کہتے ہیں.خصوصاً کلام لانے والے فرشتوں کا سردار جبرائیل روح القدس کہلاتاہے.پس اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ کے یہ معنے ہیں کہ (۱) ہم نے تقدس و برکات والے فرشتہ سے اس کی مدد کی.جو خدا تعالیٰ کے حضور سے کلام لاتا ہے یا (۲)خدا نے اُسے اپنے پاک اور مبارک کلام سے مشرف کیا اور اُسے طاقت بخشی.تفسیر.جیسا کہ حَلِّ لُغات میں بتایا جا چکا ہے لفظ قَفَّیْنَا کے معنے ہیں’’ہم نے پیچھے چلایا‘‘.اِس لفظ سے نہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سے انبیاء آئے.بلکہ یہ ظاہر کرنا بھی مطلوب ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہ تھے.بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے اور اُسی راستہ پر چلتے تھے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب ’’شہادۃ القرآن‘‘ میں اس سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ’’ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی ایسے انبیاء آئے جن کی کوئی جدید شریعت نہ تھی.بلکہ وہ تورات کے احکام پر ہی لوگوں سے عمل کرواتے اور اُسی کی تعلیم کو رائج کرتے تھے‘‘.(نفس مضمون شہادۃ القرآن روحانی خزائن جلد ۶ صفحہ ۳۴۰،۳۴۱) عام طور پر مفسّرین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے.لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے.اِسی وجہ سے علّامہ ابو حیان نے اپنی تفسیر میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی ہوئے ہیں وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے بلکہ وہ حضرت موسیٰ ؑکی شریعت ہی کے تابع ہوا کرتے تھے.چنانچہ وہ اپنی تفسیر بحِر محیط میں اس
Page 270
آیت کے ماتحت لکھتے ہیں.وَیَحْتَمِلُ اَنْ تَکُوْنَ التَّقْفِیَّۃُ مَعْنَوِیَّۃً وَھِیَ کَوْنُھُمْ یَتَّبِعُوْنَہٗ فِی الْعَمَلِ بِالتَّوْرٰۃِ وَ اَحْکَامِھَا وَیَاْمُرُوْنَ بِـاِتِّبَاعِھَاوَالْبَقَاءِ عَلٰی اِلْتِزَامِھَا.(البحر المحیط ) یعنی آیت زیر بحث میں قَفَّیْنَا کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تورات پر عمل کرنے اور اس کے احکام کو بجا لانے میں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے تھے اور لوگوں کو اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ تورات کے احکام پر پوری طرح عمل کیا جائے.اورہمیشہ اس پر عمل پیرا رہنے کی کوشش کی جائے گویا ظاہری طور پر نقشِ قدم پر چلنا ہی مراد نہیں بلکہ معنوی طور پر بھی چلنا مراد ہے.(ب) وَ اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ.بیّنات اور روح القدس کے ذریعے حضرت مسیحؑ کا تائید پانا یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں جو صرف حضرت مسیح ؑ ناصری کے ساتھ مخصوص ہوں یا اس سے دوسرے انبیاء پر اُن کی کسی فضلیت کا استدلال ہو سکے.چنانچہ قرآن کریم اِسی سورۂ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے.وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (البقرۃ :۹۳) یعنی موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے.مگر پھر بھی تم نے اُس کے (پہاڑ پر جانے کے)بعد شرک کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا.اِس سے صاف ظاہر ہے کہ اِس بارہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیّنات دیئے گئے تھے.اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَ لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ١ۚ وَ مَا يَكْفُرُ بِهَاۤ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ(البقرۃ :۱۰۰) یعنی یقیناً ہم نے تیری طرف بینات نازل کی ہیں.جن کا نافرمانوں کے سوا اور کوئی انکار نہیں کرتا.اسی طرح سورہ مومن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ کی اقوام کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ١ؕ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (المؤمن:۲۳)یعنی اُن کے ہلاک ہونے کا باعث یہ تھا کہ اُن کے پاس اپنے اپنے وقت میں ہمارے رسول بیّنات لے کر آئے تھے اور انہوں نے اُن کا انکار کر دیا تھا.پس اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتارِ بلا کر دیا.اور وہ طاقتور اور بعض شرارتوں پر فوری سزا دینے والا ہے.اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جس قدر انبیاء دنیا میں آئے سب اپنے ساتھ بیّنات بھی رکھتے تھے.اگر اُن کے ساتھ بیّنات نہ ہوتے تو وہ رسول ہی ثابت نہیں ہو سکتے تھے.پس آیت زیرِ تفسیر میں حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے نام کے ساتھ بیّنات کا ذکر کرنے سے یہ ہر گز مراد نہیں کہ ان کو اس امر میں کوئی امتیازی خصوصیت حاصل تھی بلکہ اس سے یہود کو صرف یہ بات بتلانا مدّنظر ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی اُن تمام انبیاء کی طرح جن کی صداقت کے تم قائل ہو اپنے ساتھ اپنی صداقت کے نشانات رکھتے تھے.
Page 271
اِسی طرح روح القدس کے ذکر سے یہ بتلانا مدّنظر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی دوسرے انبیاء کی طرح الہام ہوتا تھا.نہ یہ کہ اُن کو دوسرے انبیاء پر کوئی خاص فضیلت حاصل ہے.یا وہ صاحبِ شریعت نبی ہیں.اور اگر رُوح کے معنے فرشتے کے کئے جائیں اور روح القدس کے معنے پاک فرشتہ کے لئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ اُن کی تائید کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کر دیا تھا.تاکہ وہ لوگوں کے دلوں میں اُن کی قبولیت بٹھائیں یا خود اُن کے دل کو مضبوط کریں.چنانچہ ایک دوسری آیت سے اس کی تشریح ہو جاتی ہے فرماتا ہے.وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَ بِرَسُوْلِيْ(المآئدۃ : ۱۱۲) اس واقعہ کو بھی یاد کرو جبکہ میں نے حواریوں کو وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لائو.اور یہ ظاہر ہے کہ وحی عام طور پر ملائکہ کے توسط سے ہی ہوا کرتی ہے.پس ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید جبرائیل کے ذریعہ کی.اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے سب نبیوں بلکہ اعلیٰ درجہ کے مومنوں کو بھی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ؓ کی نسبت قرآن کریم میںآتا ہے.اُولٰٓىِٕكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ (المجادلۃ:۲۳) یعنی یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان راسخ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے رُوح بھیج کر اُن کی مدد کی ہے.یعنی ملائکہ کو اُن کی مدد پر مقرر فرمایا ہے.گو اس جگہ روح القدس کے الفاظ نہیں مگر رُوْحٌ مِّنْہُ کے الفاظ پائے جاتے ہیں.اور وہ رُوح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ مقدس ہی ہوتی ہے.اِسی طرح اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے.قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدًى وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ۠.(النّحل:۱۰۳) یعنی اے محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تُو لوگوں سے یہ کہدے کہ روح القدس نے اِس قرآن کریم کو تیرے رب کی طرف سے حق و حکمت کے ساتھ اُتارا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں وہ ہمیشہ کے لئے ایمان پر قائم کردے.نیز اُس نے یہ کتاب مومنوں کی مزید ہدایت اور انہیں بشارت دینے کے لئے نازل فرمائی ہے.اِسی طرح ایک اور جگہ فرماتا ہے.فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (البقرۃ :۹۸) یعنی رُوح القدس نے اِس کتاب کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے اِذن کے ساتھ نازل کیا ہے.پس بیّنات دیئے جانے اور مؤید بروح القدس ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خاص فضیلت نہیں دی جا سکتی.قرآن کریم کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بھی ثابت ہے کہ روح القدس کا نزول حضرت مسیحؑ ناصری کے علاوہ اور انبیاء بلکہ غیرانبیاء پر بھی ہو سکتا ہے.چنانچہ حضرتحسّان ؓ کا واقعہ اس پر شاہد ہے.تفصیل اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اس زمانہ کے اشرار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
Page 272
کی ازواج مطہرات کے خلاف نہایت گندی نظمیں اور اشعار بنا بنا کر پڑھا کرتے تھے.ایک مدت تک تو صحابہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق صبر سے کام لیتے رہے مگر جب وہ اِس خباثت میں حد سے بڑھ گئے تو بعض صحابہؓ نے حضرت حسّان ؓ سے خواہش کی کہ وہ ان کا جواب دیں.حضرت حسّان ؓنے اُن کے کہنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے متعلق عرض کیا.کہ یا رسول اللہ ! انہوں نے آپ پر بہت حملے کئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اُن کو جواب دوں.اور اُن کے عیوب ظاہر کروں.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب دینا اچھی بات ہے مگر اس میں ایک دِقّت ہے اور وہ یہ کہ اُن کے اور ہمارے آبائو اجداد ایک ہی ہیں.اگر تم اُن پر حملہ کرو گے تو وہ حملہ ہم پر بھی ہو گا.حضرتحسّان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا.یا رسول اللہ! میں آپ کو اور آپ کے خاندان کو اُن سے اس طرح الگ کرلوں گا جس طرح مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے.یہ اُن کے قادر الکلام ہونے کی دلیل تھی.کیونکہ قادرالکلام شاعر ہی اس رنگ میں شعر کہہ سکتا ہے کہ دوسرے کو جواب بھی دیدے اور اپنے بزرگوں پر بھی حملہ نہ ہونے دے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اُھْجُ قُرَیْشًا وَرُوْحُ الْقُدُسِ مَعَکَ (البحر المحیط زیر آیت ھذا) یعنی اے حسّان! قریش کی ہجو کر رُوح القدس تیرے ساتھ ہے.اب یہ کوئی الہام نہ تھا جس کا آپؐ نے ذکر فرمایا ہو.بلکہ بغیر الہام کے آپؐ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے.کیونکہ حسّانؓ اُس وقت دین کی تائید کے لئے کھڑے ہوئے تھے.پس رُوح القدس کے الفاظ سے کسی کا یہ سمجھنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کوئی خصوصیت حاصل تھی درست بات نہیں.اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے.کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسّان ؓ کو فرمایا.وَجِبْرِیْلُ مَعَکَ (البحرالمحیط زیر آیت ھذا) یعنی جبریل تیرے ساتھ ہے.حضرت حسّان ؓ اپنے ایک شعر میں بھی فرماتے ہیں.؎ وَ جِبْرِیْلُ رَسُوْلُ اللّٰہِ فِیْنَا وَ رُوْحُ الْقُدُسِ لَیْسَ لَہٗ کِفَاءٗ (البحرالمحیط زیر آیت ھٰذا ) یعنی اللہ کے رسول پر اُترنے والا جبریل ہم میں ظاہر ہوا ہے اور وہ ایسی پاکیزہ رُوح ہے جس کا کوئی مثیل نہیں.یعنی جبریل جو اللہ کا رسول ہے ہم میں ہے اور روح القدس کا کوئی مثیل نہیں.اس شعر کے مطابق تمام صحابہ کرامؓ کو رُوح القدس کی تائید حاصل تھی.پس صرف روح القدس کی تائید حاصل ہونے سے عیسائیوں کا یہ استدلال کرنا کہ حضرت مسیح ؑ ابن اللہ تھے یاا لٰہ تھے نادانی ہے.
Page 273
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا جواب دینے کے لئے حضرت حسّان ؓ کو فرمایا اور دُعا کی کہ اَللّٰھُمَّ اَیِّدْ ہُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ.اے خدا! روح القدس سے اس کی تائید فرما.(مشکوٰۃ المصابیح باب البیان و الشعر و کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۲،۲۳ ایڈیشن اول ) ایک اور روایت کے مطابق اُھْجُ الْمُشْرِکِیْنَ فَاِنَّ جِبْرِیْلَ مَعَکَ (بخاری کتاب المغازی باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب)یعنی اے حسّان ؓ !مشرکین کی ہجو کر جبریل تیرے ساتھ ہے.پس حضرت مسیح ؑ کا روح القدس سے مؤید ہونا اُن کی کسی فضیلت کا ثبوت نہیں اس میں تمام انبیاء بلکہ غیر انبیاء بھی شریک ہیں.اَور سب کو اپنے اپنے درجہ اور مقام کے مطابق رُوح القدس کی تائید حاصل ہوتی ہے.حضرت معین الدین صاحب چشتی (رحمۃ اللہ علیہ) جو امّتِ محمدیہ ؐکے ایک مسلّمہ بزرگ ہیں وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ؎ دمبدم رُوح القدس اندر معینے می دمد من نمی دانم مگرمن عیسیٰ ءِ ثانی شدم (دیوان حضرت خواجہ معین الدّین صاحب چشتی صفحہ۵۶) یعنی رُوح القدس بار بار میرے اندر اس طرح نفخ ِرُوح کر رہا ہے کہ شاید مجھے عیسیٰ ثانی کا مقام حاصل ہو گیا ہے.پس حضرت مسیح ؑ کا مؤید بروح القدس ہونا کوئی قابلِ تعجب امر نہیں.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے.اور وہ یہ ہے کہ وَاٰتَیْنَا عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَاَیَّدْنٰـہُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ میں اگر حضرت مسیح ؑ ناصری کی کوئی امتیازی خصوصیت بیان نہیں کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد باقی سب انبیاء کا مجموعی ذکر کرنے کے بعد حضرت مسیح ؑ کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا ہے اور اُن کے متعلق یہ مخصوص طو رپر کیوں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے عیسٰی ؑبن مریم کو بیّنات دیں اور اس کی رُوح القدس سے تائید کی؟ عیسائی تو اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ ان کو دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل تھی اور وہ دوسروں سے بالا مقام رکھتے تھے اس لئے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے.اگر وہ بھی رسول ہی ہوتے تو اُن کا الگ ذکر نہ کیا جاتا.لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرے انبیاء کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے بلکہ موسوی شریعت کے تابع تھے اس لئے ان کا اکٹھا ذکر کیا گیا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت موسوی کے متبع نہیں تھے بلکہ وہ ایک نئی شریعت لائے تھے اس لئے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا ہے مگر یہ صحیح نہیں.کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود کہا ہے کہ
Page 274
’’یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں.منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں.کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا.جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے‘‘ (متی باب۵ آیت۱۷،۱۸) پس یہ تو غلط ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا علیحدہ ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ آپ صاحبِ شریعت جدیدہ تھے.لیکن یہ سوال ضرور قائم رہتا ہے کہ اگر بینات دیئے جانے اور روح القدس سے مؤید ہونے میں اُن کی کوئی خصوصیت نہیں تھی تو پھر ان کا علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا.سو یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل میں جس قدر انبیاء حضرت مسیح ؑ سے پہلے گزر چکے ہیں اُن کی عظمت کے بنی اسرائیل کسی نہ کسی رنگ میں ضرور قائل تھے.اور گوابتدا میں اُن کی مخالفت بھی ہوئی لیکن بعد میں اُن کی صداقت کو یہودیوں نے قبول کرلیا تھا.چنانچہ بائیبل میں ملا کی نبی تک سب انبیاء کی کتب موجود ہیں.جن کو وہ پڑھتے اور قابل عمل سمجھتے ہیں.حتیّٰ کہ حضرت دائود ؑ اور حضرت سلیمان ؑ جن کے آخر عمر میں مرتد ہونے کے وہ قائل ہیں ان کا ذکر بھی بائیبل میں موجود ہے اور ان کے اعمال کو نظر انداز کرتے ہوئے اُن کے کلام کی اُن میں اَب تک قدر پائی جاتی ہے.اِسی طرح حضرت زکریاؑ اور یحییٰ ؑ کو بھی گووہ نبی تسلیم نہیں کرتے لیکن عالم اور نیک آدمی سمجھتے ہیں.پس سب انبیاء کی عظمت کے وہ قائل ہیں گو بعض کو بحیثیت عالم اور نیک ہی مانتے ہیں لیکن حضرت مسیح ؑ کی نسبت اُن کا عقیدہ نہایت گندہ اور ناپاک ہے.وہ آپ پر خطرناک الزام لگاتے ہیں اور نعوذ باللہ مفتری اور ملعون قرار دیتے ہیں.پس یہود نے نبیوں کی جو مخالفت کی تھی اُس کا ذکر کرتے ہوئے ضروری تھا کہ حضرت مسیحؑ کا ذکر دوسرے انبیاء سے علیحدہ اور خاص طور پر کیا جاتا کیونکہ اُن کے ساتھ انہوں نے سب سے بُرا سلوک کیا تھا.اور قرآن کریم کے نزول تک اپنے اس عقیدے پر قائم تھے کہ نعوذ باللہ آپ مفتری تھے.اور صداقت سے آپ کو کوئی حصہ نہیں ملا تھا.اسی طرح حضرت مسیح ؑ سے یہود کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا بتلا دینا بھی ضروری تھا کہ گو یہود انہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں لیکن وہ اپنے ساتھ صداقت کی وہ تمام علامتیں رکھتے تھے جو دوسرے راستباز انبیاء جن کی نبوت کے بنی اسرائیل قائل ہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے.چنانچہ انبیاء کی صداقت کی زبردست علامات میں سے دو کو حضرت مسیح ؑ کے ذکر کے ساتھ بیان کر دیا جن میں سے پہلی علامت آپ کے ساتھ بینات یعنی کھلے کھلے نشانات کا ہونا ہے جو ہر نبی کی صداقت کے اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور دوسرے روح القدس کی تائید ہے کہ یہ بھی ہر نبی کے لئے ضروری ہے.بینات اور روح القدس کا ذکر اس
Page 275
لئے بھی کیا گیا ہے کہ یہودی حضرت مسیح ؑ پر یہی دو۲ اعتراض کیا کرتے تھے.کہ اوّل اُس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا.دومؔ وہ نعوذ باللہ ناپاک تھا اور اُس پر شیطانی رُوح آتی تھی.چنانچہ معجزہ نہ دکھانے کے اعتراض کا ذکرمتی باب ۱۲ آیت۳۸ تا ۴۰ میں اس طرح آتا ہے کہ ’’تب بعضے فقیہیوں اور فریسیوں نے جواب میں کہا.کہ اے اُستاد! ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں.اُس نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرامکار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں.پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جائے گا.کیونکہ جیسا یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسا ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا.‘‘ اور شیطانی رُوح کے متعلق یہود کے الزام کا ذکر لوقا باب۱۱ آیت۱۴‘۱۵ میں آتا ہے.لکھا ہے.’’پھر وہ ایک گونگی رُوح کو نکال رہا تھا.اور جب وہ بد رُوح نکل گئی تو ایسا ہوا کہ گونگا بولا اور لوگوں نے تعجب کیا.لیکن ان میں سے بعض نے کہا.یہ تو بدرُوحوں کے سردار بعلزبول کی مدد سے بدرُوحوں کو نکالتا ہے.‘‘ بلکہ لوگوں نے حضرت مسیح ؑ کا نام ہی بعلزبول رکھ دیا تھا.چنانچہ وہ اپنے شاگردوں کو صبر کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ’’جب اپنوں نے گھر کے مالک کو بعلزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے.‘‘ (متی باب۱۰آیت۲۵) پس اٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِمیںیہود کے پہلے اعتراض کا رد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح ؑ کے ہاتھ پر ہم نے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے تھے.گو افسوس ہے کہ انجیل آپ کے وہ معجزات پیش نہیں کرتی جو یہود کے مقابلہ میں حضرت مسیح ؑ کی صداقت کی دلیل ہو سکتے.آپ کا صرف ایک ہی معجزہ تھا اُسے بھی عیسائیوں نے اپنی نادانی سے مشتبہ کر ڈالا.وہ معجزہ وہی تھا جس کا حضرت مسیح ؑ نے خود ذکر کیا تھا.اور کہا تھا کہ انہیں یونس نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا.حضرت یونس ؑ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور زندہ ہی نکلے.مگر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر ہی مر گئے تھے اور مر کر ہی قبر میں گئے تھے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے.اِس معجزہ کے دو۲ حصے تھے.ایک حصہ بندوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اسے خود عیسائیوں نے مشتبہ کر دیا.دوسرا حصہ کہ وہ زندہ ہو گئے اُسے یہود مانتے ہی نہ تھے.گویا ایک ہی معجزہ جو حضرت مسیح ؑنے
Page 276
دکھانے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی انجیل کے مطابق نہ دکھایا جا سکا.ایک حصہ کے متعلق تو عیسائیوں نے مان لیا کہ وہ غلط نکلا ہے اور دوسرا حصہ یہود کے لئے حجت نہیں ہو سکتا تھا.پس بیّنات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اُن کے اعتراض کا رد کیا ہے.باقی انبیاء کے متعلق تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ اُن پر تو یہ اعتراض ہی نہ ہوا تھا.صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہو اتھا.پس اس اعتراض کا رد کرنے کے لئے خاص طور پر فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح ؑ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا یہ غلط ہے.ہم نے اُن کوبہت سے معجزات اور بیّنات دے کر مبعوث کیا تھا.دوسرا اعتراض یہ تھا کہ حضرت مسیح ؑ پر نعوذ باللہ شیطانی رُوح کا نزول ہوا کرتا تھا.اس کا رد اللہ تعالیٰ نے اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِکے ذریعہ کیا.جس طرح عیسائیوں نے حضرت مسیح ؑ کے ایک ہی معجزہ کو یہ کہہ کر باطل کر دیا کہ حضرت مسیحؑ صلیب پر مر گئے تھے اور مر کر ہی قبر میں گئے اسی طرح انہوں نے یہود کے اس اعتراض کو بھی پختہ کر دیا کہ حضرت مسیح ؑ کا نعوذباللہ شیطان سے تعلق ہے.کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ شیطان نے حضرت مسیحؑ کا امتحان لیا(متی باب۴) اب بھلا شیطان کو ایک نبی کا امتحان لینے کی جرأت ہی کیسے ہو سکتی ہے.بلکہ وہ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا.مگر انہوں نے انجیل میں اس کا ذکر کر کے یہود کے اِس اعتراض کو اور بھی مضبوط کر دیا.کہ حضرت مسیح ؑ کا شیطان سے تعلق تھا.پس چونکہ اس اعتراض کا بھی کسی اور نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسیح ؑ کا الگ ذکر کر کے اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ فرما دیا.اور اس اعتراض کو باطل کر دیا کہ جو یہود آپ کی ذات پر کرتے تھے.یہاں تک تو یہود کے نقطۂ نگا ہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا جواب دیا گیا ہے.کہ حضرت مسیح ؑ کا باقی انبیاء سے علیحدہ کیوں ذکر کیا گیا ہے.اب میں عیسائیوں کے نقطۂ نگاہ کو مد نظر رکھ کر جواب دیتا ہوں.جیسا کہ میں نے بتایا ہے.عیسائی اس آیت سے فائدہ اُٹھا کر حضرت مسیح ؑ کو ابن اللہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں.وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت مسیح ؑ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے تو اُن کو وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ میں پہلے ہی شامل کر لیا گیا تھا پھر ان کا الگ ذکر کیوں کیا گیا.ان کا الگ ذکر کرنا بتاتا ہے کہ اُن کو رسولوںسے بالا ہستی قرار دیا گیا ہے.اِس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ انبیاء جن کو وَ قَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِمیں بیان کیا گیا ہے.اُن کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی الگ جماعتیں موجود نہ تھیں مثلاً حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی جماعت نہ تھی.حضرت سلیمان ؑکی کوئی جماعت نہ تھی.حضرت یحییٰ ؑ کی کوئی جماعت نہ تھی.حضرت الیاس ؑ کی کوئی جماعت نہ تھی.حضرت زکریا ؑ کی کوئی جماعت نہ تھی.اسی طرح دانی ایل اور حزقی ایل کی کوئی جماعت نہ تھی.پس ان کا الگ ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرور ت نہ تھی.لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت یہود سے الگ موجود تھی اس لئے ضروری تھاکہ ان کا علیحدہ ذکر کیا
Page 278
کہ وہ مخلوق تھے نہ کہ خالق.اور مخلوق الٰہ نہیں ہوسکتی.اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ وہ دوسرے کی مدد کے محتاج تھے.اور جو دوسرے کی مدد کا محتاج ہو وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے.طاقت اور قوت تو اسی کو بخشی جاتی ہے جو کمزور اور ضعیف ہو.پس اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ کے الفاظ بھی حضرت مسیحؑ کی کمزوری کو ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ روح القدس کی تائید کی ضرورت تبھی تسلیم کی جا سکتی ہے جبکہ پہلے ان کی کمزوری مانی جائے.اور جو ہستی کمزور اور ضعیف ہو وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہلا سکتی.پس یہ فقرہ خود ان کی ذات میں اُن کی خدائی کی تردید کر رہا ہے.اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انہیں پاکیزگی کی قوت خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی.اگر خدا تعالیٰ ان کو پاکیزگی عطا نہ کرتا تو وہ صرف گوشت پوست کا ایک لوتھڑا ہوتے.پس یہ فقرات حضرت مسیح کی الوہیت کا ثبوت نہیں.بلکہ اُن کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے والوں پر ایک کاری ضرب ہیں.اَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ الخ.اِس میں بتایا کہ نبی تو اس وقت آتا ہے جب کہ لوگ صحیح راستہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں.اور اس وجہ سے لازماً اس کی تعلیم لوگوں کے خیالات کے خلاف ہوتی ہے.لیکن یہود نے اپنی یہ عادت بنا رکھی ہے کہ جو بات اپنی رائے کے مخالف ہو اسے قبول نہیں کرنا.اس لئے ہر رسول کے آنے پر انہوں نے تکبّر سے کام لیا.اور اگر ایک حصہ کو صرف زبان سے جھٹلا دیا تو دوسرے حصہ کو قتل کرنے تک کے منصوبے کئے.اللہ تعالیٰ یہود کی اس شقاوت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب تم نے انکار ہی کرنا ہے تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ اگر بنی اسحاق میں سے نبی ہوتا توہم اُسے مان لیتے کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے.یہ تو تمہارا صریح جھوٹ ہے.فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ١ٞ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ کے یہ بھی معنے ہو سکتے ہیں کہ تم نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا.جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا.مگر كَذَّبْتُمْ اورتَقْتُلُوْنَ کے صیغوں میں چونکہ فرق کر دیا گیا ہے اس لئے فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کا ارادۂ قتل بھی ہو سکتا ہے.یعنی پچھلوں کو تم نے جھٹلایا اور اس نبی کو تم قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو.یا اس سے لڑائی کرتے ہو.اس صورت میں اس کے معنے قتل کے نہیں بلکہ لڑائی کے ہوں گے.بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا گند کم نہیں ہوا بلکہ اور بھی بڑھ گیا ہے اور جہاں تک تمہارا بس چلا ہے تم نے خدا تعالیٰ کے نبیوں کی مخالفت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی.
Page 279
وَ قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ١ؕ بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا اور( ہمیں معلوم ہے کہ) انہوں نے (یہ بھی) کہا ہے( کہ) ہمارے دل تو پردوں میں ہیں.(مگر یہ بات ) نہیں مَّا يُؤْمِنُوْنَ۰۰۸۹ بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کی ہے.پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں.حَلّ لُغَات.غُلْفٌ.اَغْلَفُ کی جمع ہے.اور غِلَافٌ کی بھی.اس کے معنے نامختون کے ہیں.لیکن اِس کے علاوہ عربی زبان میں دو۲ عام محاورے بھی ہیں.کہتے ہیں(۱) قَلْبٌ اَغْلَفُ یعنی ایسا دل جو اپنے اندر سمجھ نہ رکھتا ہو.اور (۲) سَیْفٌ اَغْلَفُ یعنی تلوار ایسے غلاف میں ہے کہ جس میں باہر سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی.(اقرب) تفسیر.جب کسی صداقت کا مقابلہ دلائل کے ساتھ کوئی انسان نہ کر سکے اور اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو وہ اِدھر اُدھر کی باتیں بنا کر اُسے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے.اِس آیت میں یہود کا ایک ایسا ہی عذر بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ اسلام سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے تھے.اور اس زمانہ میں بھی ضِدی لوگ اسی قسم کے عذرات کر کے اپنے آپ کو اس صداقت سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ دنیا میں بھیجی گئی ہے.جیسا کہ حلِّ لغات میں بتایا جا چکا ہے.غُلْفٌ اَغْلَفُ کی بھی جمع ہے جس کے معنے نا سمجھ کے ہیں اور غِلَافٌ کی بھی جمع ہے.اگر غُلْفٌ کو غِلَافٌ کی جمع سمجھا جائے تو اس کا یہ مطلب ہو گا.کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز کی طرح پردہ میں رکھا ہوا ہے.تمہاری باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر سکتیں.غلاف چونکہ اعلیٰ درجہ کی چیزوں پر چڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ میلی نہ ہوں اس لئے قُلُوْبُنَا غُلْفٌکا فقرہ کہہ کر اُن کا منشاء یہ ہوتا کہ تم ہمیں کیا سمجھاتے ہو ہمارے دل تو خود بڑے پاک اور ہر قسم کی آلا ئشوں سے مبرّا ہیں.اِس لئے تمہاری باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا.خدا تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اثرات سے محفوظ رکھا ہوا ہے.اور اگراس کے معنے نا سمجھ کے لئے جائیں.تو قُلُوْبُنَا غُلْفٌکا یہ مفہوم ہو گا کہ مسلمان جب اُن کے سامنے دلائل پیش کرتے تو وہ اپنا پیچھا چھڑانے کے لئے کہہ دیتے کہ یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں مگر ہم ناسمجھ اور جاہل ہیں بھلا ہم ان
Page 280
باتوں کو کہاں سمجھ سکتے ہیں.اس سے بعض لوگوں کی تو یہ مراد ہوتی کہ ہم کسی بحث میں نہیںپڑنا چاہتے.تم ہمارے علماء کو سُنائو اور سمجھائو ہمارے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرو.اور بعض لوگ طنز کے طو پر کہتے کہ آپ لوگ تو بڑے عالم ہیں.ہم جاہل لوگ ہیں یہ باتیں ہمیں کہاں سمجھ آسکتی ہیں.جس کا دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہوتا کہ ہم لوگ جو سمجھدار ہیں جب ہماری سمجھ میں بھی یہ باتیں نہیں آتیں تو تم کیونکر سمجھ گئے.یا یہ کہ تمہارے نزدیک ہمارے دل غلاف میں ہیں یعنی سزا کے طور پر اُن پر پردے پڑے ہوئے ہیں.پھر ایسی صورت میں تم کیوں سمجھانے آتے ہو.اگر غُلْفٌ کے معنے علم کے خزانہ کے لئے جائیں.تو یہودیوں کا ان الفاظ سے یہ مطلب ہوتا کہ ہمارے دل تو علم کے خزانے ہیں ہمیں کسی مزید صداقت کی کیا ضرورت ہے.قُلُوْبُنَا غُلْفٌ کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دل ناپاک ہیں.یعنی جب انہیں کوئی جواب نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم گندے لوگ ہیں ہمیں چھوڑو اور کسی اَور سے گفتگو کرو گویا مسلمانوں سے وہ اپنا پیچھا چھڑانے کے لئے ایسا کہتے ہیں حالانکہ ہدایت تو آتی ہی ایسے لوگوں کے لئے ہے جو گندے ہوں.یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قُلُوْ بُنَا غُلْفٌ بطور تنفّرکے کہتے ہوں.یعنی جب تم ہمیں گندہ اور ناپاک سمجھتے ہو تو ہمیں نصیحت کیوں کرتے ہو.بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ فرماتا ہے یہود کا اِن الفاظ سے خواہ کچھ بھی مطلب ہو.خواہ وہ بات کو ختم کرنے کے لئے ایسا کہیں خواہ طنزاً ایسا کہیں خواہ اپنی علمیت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لئے ایسا کہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت پڑ گئی ہے اور اسی لعنت کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ قبول حق سے محروم ہو گئے ہیں.بِكُفْرِهِمْ میں بتایا کہ یہ لعنت اُن پر اس لئے پڑی ہے کہ انہوں نے متواتر اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا انکار کیا اور اُن کی مخالفت کی.پس نہ تو یہ ایسے نا سمجھ ہیں کہ بات کو سمجھ ہی نہ سکیں اور نہ ہی اعلیٰ درجہ کے سمجھدار وجود ہیں کہ کسی کی تبلیغ کے محتاج ہی نہ ہوں.اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر لعنت ڈال دی ہے.اس وجہ سے باوجود اس کے کہ اسلام کی تعلیم دوسری تمام تعلیموں سے افضل ہے اور فطرت انسانی اس کو قبول کرتی ہے اور عقلِ سلیم اس سے مطمئن ہوتی ہے پھر بھی وہ اس کا انکار کر رہے ہیں.لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْکے الفاظ اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کسی پر بلاوجہ نہیں پڑتی بلکہ اس کا اصل باعث کفر ہوتاہے.ورنہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بے حد رحم و کرم سے کام لینے والا ہے انہیں اپنی محبت سے محروم نہیں کرتا.وہ اسی وقت اپنے قرب کے دروازے ان پر بند کرتا ہے جب وہ خود اس کی رحمت کے دروازوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں.
Page 281
فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ.اِس کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں.یہ بھی کہ وہ تھوڑا ایمان لاتے ہیں یعنی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو ردّ کر دیتے ہیں.جیسے یہود کے متعلق پچھلے رکوع میں آچکا ہے کہ یُؤْ مِنُوْنَ بِبَعْضِ الْکِتٰبِ وَیَکْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ یعنی وہ احکامِ الہٰی میں سے بعض کو تومان لیتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں.پس اِس کے ایک معنے تو یہ ہیں کہ وہ ناقص طور پر ایمان لاتے ہیں.لیکن اِس کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بالکل ایمان نہیں لاتے.کیونکہ نفی کے لئے بھی قلیل کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں.علّامہ ابو البقاء نے لکھا ہے کہ اس کے معنے اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ مَا نافیہ مانا جائے اور اصل عبارت یوں سمجھی جائے کہ مَایُؤْمَنُوْنَ قَلِیْلًا وَ لَا کَثِیْرًا.مگر اس صورت میں بھی معنے ایک ہی رہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان سے بالکل محروم ہو چکے ہیں.وَ لَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ١ۙ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب آئی جو اس (کتاب کی پیشگوئیوں ) کو جو ان کے پاس ہے وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ۠ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا١ۖۚ فَلَمَّا سچا کرنے والی ہے تو باوجود اس کے کہ پہلے یہ( لوگ اللہ سے)کافروں پر فتح (پانے کی دعا ) مانگا کرتے تھے جب جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ١ٞ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ۰۰۹۰ ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کو انہوں نے پہچان لیا تو اس کا انکار کر دیا پس ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے.حَلّ لُغَات.یَستَفْتِحُوْنَ.اِسْتَفْتَحَ فُلَانٌکے معنے ہوتے ہیں طَلَبَ الْفَتْحَ وَاسْتَنْصَرَ اُس نے فتح اور نصرت چاہی.اور اِسْتَفْتَحَ الْبَابَ کے معنے ہوتے ہیں فَتَحَہٗ اُس نے دروازہ کھولا.(اقرب) تفسیر.مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ.یاد رکھنا چاہیے کہ تصدیق دو قسم کی ہوتی ہے.ایک قسم تو یہ ہے کہ مثلاً ہم کہیں کہ زید سچا ہے.اس کا یہ مطلب ہو گا کہ زید کی طرف جھوٹ منسوب نہیں ہو سکتا.اور دوسری قسم یہ ہے کہ زید کہے بکرآجائے گا اور وہ آجائے.تو ہم کہیں کہ بکر نے زید کو اپنی بات میں سچا کر دیاہے.یعنی اُس نے زید کی بات سچی ثابت کر دی.اس جگہ بھی تصدیق کے یہ معنے نہیں کہ قرآن کریم نے تورات کی ساری تعلیم کو سچا قرار دے دیا ہے بلکہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ پیشگوئیاں جو بائیبل میں قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پائی جاتی تھیں قرآن کریم نے اپنے نزول سے اُن کو سچا ثابت کر دیا ہے.پس یہ تصدیق پیشگوئیوں کے بارہ میں ہے.یہ
Page 283
نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تھا کافر کہنے لگ گئے.حالانکہ اس سے قبل آنے والے رسول کے متعلق وہ اپنی کتابوں سے خود پیشگوئیاں نکال نکال کر بیان کیا کرتے تھے.اور اس بات پر فخر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ موعود نبی آئے گاتو پھر ہم تمہاری خوب خبرلیںگے لیکن جب وہ رسول آگیا تو وہ تاویلیں کرنے لگ گئے.یہی حال آج کل کے مسلمانوں کا ہے.وہ بھی کفار پر غلبہ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے.مگر جب آنے والا آگیا تو وہ تاویلیں کرنے لگ گئے اور پھر یہ کہنے لگ گئے کہ یہ خیالات ہمارے اندر مجوسیوں سے آگئے ہیں.ورنہ دراصل ہمارے ہاں کوئی ایسی پیشگوئی ہی نہ تھی.فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.اس جگہ کافر سے مراد عام کافر بھی ہو سکتے ہیں.مگر زیادہ تر وہی کافر مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو یہ دُعائیں کیا کرتے تھے کہ الہٰی کوئی ایسا رسول مبعوث فرما جو دین حق کو ادیانِ باطلہ پر غالب کر دے لیکن جب وہ رسول آگیا.اور ان لوگوں نے علامات سے یہ بات دیکھ لی کہ باطل پر صداقت غالب آرہی ہے اور عنقریب کلّی طور پر غالب آجائے گی تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا.پس واضح صداقت کو دیکھ کر اور حجت قائم ہونے اور دُعائیں کرنے کے بعد اُن کے انکار کرنے کے یہ معنے ہیں کہ اُن پر خدا تعالیٰ کی لعنت پڑی ہوئی ہے.ورنہ ایسی واضح صداقت کا وہ بلا وجہ کس طرح انکار کر سکتے تھے.واقعہ میں جب ہم اس بات پر غور کریں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کس طرح حضرت موسیٰ ؑ اور دوسرے اسرائیلی نبیوں کی عزت عرب کے دلوں میں بیٹھ گئی اور وہ جو اُن انبیاء کو مفتریوں کی طرح سمجھتے تھے صادقوں کی طرح اُن کی عزت کرنے لگے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہود کو آخر وہ کونسی تکلیف پہنچی تھی جس کی وجہ سے ایسے محسن انسان کی دشمنی اور ایذاء دہی میں انہوں نے عرب کے کفار سے بھی زیادہ زور لگایا.بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وہ امر بہت ہی برا ہے جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ رکھا ہے.اور وہ ان کا اللہ کے اتارے ہوئے بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ١ۚ کلام سے اس بات پر بگڑ کر انکار کرنا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے (کیوں) اپنا فضل نازل کردیتا
Page 284
فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ١ؕ وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ۰۰۹۱ ہے.پس یہ لوگ غضب کے بعد غضب کا مورد ہوگئےاور ایسے (ہی) کافروں کے لئے رسوا کرنے والا عذاب (مقدّر) ہے.حَلّ لُغَات.اِشْتَرٰی.یہ لفظ خریدنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنوں میں بھی.یہاں دونوں معنے چسپاں ہو جاتے ہیں.(اقرب) تفسیر.بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ.یہ ایک وسیع مضمون ہے جو لمبی تفصیل سے تعلق رکھتا ہے مگر میں اسے اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں.قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اس وقت اللہ اور اس کے درمیان ایک سودا ہو جاتا ہے.جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرماتا ہے.اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (التوبة :۱۱۱) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اُن کی جانیں اور اُن کے اموال اس وعدہ کے ساتھ خرید لئے ہیں کہ انہیں اس کے بدلہ میں جنت دی جائے گی.اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیتا ہے اور اس کی قیمت میں انہیں جنت دے دیتا ہے.جنت مرنے کے بعد ملنے والی چیز ہے.اور جو چیز بعد میں ملنے والی ہوتی ہے اس کے لئے سودا کرتے وقت کوئی نہ کوئی رسید دی جاتی ہے جسے وہ موقع پر دکھا سکے.اس نکتہ نگا ہ سے جنت کے لئے بھی کوئی پروانہ ہونا چاہیے تھا جسے وہ موقع پر دکھا کر داخل ہو سکے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں.قرآن مجید میں دوسری جگہ جنت کیلئے ایک پروانہ بھی مقرر کیا گیا ہے.فرماتا ہے.یٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ.ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ.وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.(الفجر: ۲۸تا۳۱)یعنی اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں رجو ع کر کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو گویا یہ علامت ہو گی اس بات کی کہ سودا ٹھیک ہے.چونکہ دینے والا اور لینے والا دونوں راضی ہوں گے اسلئے ثابت ہو جائے گا کہ سودا بالکل درست ہے.غرض ایمان لانا ایک سودا ہے جو بندہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر لیتا ہے.اور اس کےلئے پہلے اسے ایک پروانہ دے دیتا ہے اور وہ پروانہ یہ ہے کہفَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا.گویا عبودیت کا مقام وہ ٹکٹ ہے جسے دکھا کر ایک مومن بندہ جنت میں داخل ہو جائےگا.
Page 285
ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ (الانعام : ۱۲۶) یعنی جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے اور کامیاب کرنا چاہتا ہے اور جنت میں پہنچانا چاہتا ہے.اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے.اسلام کا لفظ بعض دفعہ ایمان کے لئے بھی استعمال ہوجاتا ہے.اور بعض دفعہ ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں.اس جگہ اسلام کا لفظ ایمان کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بتایا گیا کہ جسے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانا چاہتا ہے.اُس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے گویا سینے کا کھلنا بھی جنت کا ایک ٹکٹ ہے.غرض ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے عبودیت کے ٹکٹ کا ذکر کیا ہے اور دوسری جگہ شرح صدر کو اُس کی علامت قرار دیا ہے.دراصل یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں.کیونکہ تعبّد کے معنے تذلّل اور خدا کے نقش کو قبول کرنے کے ہیں اور عبدکامل وہ ہو تا ہے جو خدا تعالیٰ کے نقش کو قبول کرنے لگ جائے اور یہی معنے شرح صدر کے ہوتے ہیں.غرض یہ ایک ثابت شدہ امر ہے کہ انسان کا مومن ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا ہو جاتا ہے.اور وہ اپنا مال اور اپنی جان خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اُسے جنت دے دیتا ہے جنّت چونکہ مرنے کے بعد ملا کرتی ہے اس لئے اس دنیا میں اس کے لئےاُسے ٹکٹ دے دیا جاتا ہے کہ اسے دکھانا اور اندر چلے جانا ورنہ اُسے کیا پتہ لگ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اُسے جنت ملے گی یا نہیں.اس لئے اس کی علامت مقرر کر دی جو عبودیت اور اسلام کے لئے شرح صدر ہے گویا ایمان و اسلام ایک ٹکٹ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو ملتا ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا سودا خدا تعالیٰ سے طے پا گیا ہے.جب وہ اسے پیش کر دیتا ہے تو اُسے جنت مل جاتی ہے.اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سودا کو فسخ کرنا چاہے تو کیا کرے.اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اُسے کہے گا کہ جنت کا ٹکٹ واپس کر دو.اور اپنی چیز لے لو.حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اُن پر ایمان لائی تو اُس کا خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُسے جنت کے لئےٹکٹ مل گیا.اِسی طرح جب عیسائی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو اس کا بھی خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیاتھا.اور اسے جنت کا ٹکٹ مل گیا.یہ لوگ اپنے اپنے زمانہ میں مومن تھے اور ان کا خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا تھا.اسی طرح مسلمانوں کا بھی خدا تعالیٰ سے سودا ہو گیا اور اُن کو بھی خدا تعالیٰ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا.مگر یہود نے یہ حماقت کی کہ انہوں نے اس بیع کو فسخ کر دیا.اور جنت کا ٹکٹ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا واپس کر دیا اور اپنی جانوں اور مالوں کو لے لیا.خدا کی دی ہوئی چیز ایمان اور اسلام واپس کر دی اور اپنی جانیں اور اموال لے لئے.اللہ تعالیٰ
Page 288
وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَاۤ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ( تعالیٰ) نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤتو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ١ۗ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا ہےاور (یہ کہتے ہوئے )اس کے بعد آنے والے (کلام) کا وہ انکار کر دیتے ہیں لِّمَا مَعَهُمْ١ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ حالانکہوہ اس (کلام ) کو جو ان کے پاس ہے سچّا کر کے کامل طور پر سچّا (ثابت ہو چکا) ہے تو (ان سے )کہہ کہ اگر تم كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۰۰۹۲ (واقعی) مومن ہو تو پھر تم کیوں اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کے قتل کے در پے رہے ہو.تفسیر.یہود کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بات پر غصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سوا دوسروں میں اپنا نبی کیوں بھیج دیا.چنانچہ جب اُن سے کہا جاتا کہ قرآن مجید میں جو کچھ اُترا ہے اُس پر ایمان لاؤتو وہ کہتے کہ ہم تو اُسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہو ا ہے.حالانکہ وہ اس بات میں بھی جھوٹے تھے.اگر وہ موسیٰ ؑ کی کتاب پر سچے دل سے ایمان رکھتے تھے اور نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا کہنے میں راستی پر تھے تو اُن پیشگوئیوں کا وہ کیوں انکار کرتے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق اُن کی کتاب میں پائی جاتی تھیں.اُن کا اپنی کتاب کی پیشگوئیوں کو جھٹلا دینا بتاتا ہے کہ وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے تھے کہ ہم صرف اپنی کتاب پر ایمان رکھیں گے.ورنہ اگر اُن میں دیانتداری پائی جاتی تو وہ سمجھتے کہ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو خود اُن کے مذہب پر حملہ ہو گا کیونکہ اُن کی اپنی کتاب میں ایک آنے والے رسول اور ایک جدید کتاب کا ذکر ہے.اور وہ نشانیاں جو اس رسول اور اِس کتاب کی بتائی گئی ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم اور قرآن کریم پر حرف بحرف منطبق ہوتی ہیں.پس اُن کا اِنکار درحقیقت اپنی کُتب کی صداقت سے بھی انکار کرنا ہے.کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ علامات باطل تھیں اور جھوٹے آدمی میں بھی پائی جا سکتی تھیں.یا یہ کہ نعوذباللہ اللہ تعالیٰ کے سوا شیطان بھی غیب کی باتیں بتا سکتا ہے.او ر اُس نے پہلے انبیاء کو آنے والے رسول کی نسبت بعض ایسی علامات بتادیں
Page 289
جو ایک جھوٹے نبی میں پائی جاتی تھیں.نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا سے یہ امر بھی مستنبط ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص پر کوئی ایسا انعام نازل ہو جس سے سار ی قوم کو فائدہ پہنچے تو اُس وقت ایسا ہی سمجھا جاتاہے.کہ گویا وہ انعام ساری قوم کو ملا ہے.چنانچہ دیکھ لو تورات یہود پر نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی.مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اُتری.کیونکہ اس کتاب سے تمام یہود نے بحیثیت قوم فائدہ اٹھایا تھا.افسوس ہے کہ اِس زمانہ میں مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو مان کر مرزا صاحب کی کیا ضرورت ہے ؟گویا وہ بھی نُؤْمِنُ بِمَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ يَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ کے مصداق بنتے ہیں.وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ.فرماتا ہے.کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری یہ تعلیم حق ہے یعنی ایک اٹل صداقت ہے جو دنیا میں نمایا ں ہو کر رہے گی.عربی زبان میں سچائی کے اظہار کے لئے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں.وہ سب دوام پر دلالت کرتے ہیں.یعنی ایسی بات پر جو نہ ٹلنے والی ہو اور پوری ہو کر رہنے والی ہو.پس هُوَ الْحَقُّ میں بتایا کہ یہ دائمی صداقت ہے جو کبھی نہیں ٹلے گی.اِسکا انکار تم کو کیا فائدہ دے گا.کیوں نہ تم اسے پہلے ہی مان لو.اصل بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے متعلق جو پیشگوئیاں بائیبل میں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب قرآن کریم کے ذریعہ پوری ہوئی ہیں اور اِسی کے ذریعہ سچّی ثابت ہوتی ہیں.اِن میں سے بعض پیشگوئیاں عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں.مگر ان پیشگوئیوں کی علامات بتا دیتی ہیں کہ ان کا حضرت مسیح ؑ پر چسپاں کرنا غلطی ہے.اس بارہ میں سب سے پہلی پیشگوئی استثنا باب۱۸آیت ۱۷تا ۱۹ کی ہے.یہ پیشگوئی اتنی واضح ہے کہ اِسے کسی صورت میں بھی کسی اور پرچسپاں نہیں کیا جا سکتا.واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ ؑ بنی اسرائیل کو طور کے دامن میں لے گئے تو بائیبل میں لکھا ہے کہ آسمان پر متواتر بجلی چمکنی شروع ہوئی اور اُس سے زور زور کی آوازیں پیدا ہوئیں.بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ ؑ سے کہنے لگے کہ تو خود جا اور خدا سے کلام کر ہم اُس کا کلام سننا نہیں چاہتے اور نہ ہماری اولادیں اُسے سنیں.تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اِن کو کہہ دے کہ میں نے ان کی بات سن لی ہے.اَب میں ان سے وہی معاملہ کرونگا جو وہ چاہتے ہیں.یعنی آئندہ میں اِن میں سے شرعی نبی برپا نہیں کرونگا.بلکہ ان کے بھائیوں سے برپا کرونگا.یہ پیشگوئی حضرت مسیح ؑ پر کسی صورت میں بھی چسپاں نہیں ہو سکتی.اگر اسے اُن پر چسپاں کیا جائے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
Page 290
کی مانند ہیں.حالانکہ یہ بات غلط ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرعی نبی نہ تھے.اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تھے.اِس کی دلیل حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ قول ہے جو انجیل میں آتا ہے کہ ’’یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں.منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں.کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہر گز نہ ٹلے گا.جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے ‘‘.(متی باب ۵آیت ۱۷، ۱۸) لیکن اگر بفرض محال حضرت مسیح ؑ کو شرعی نبی بھی مان لیا جائے تب بھی وہ موسیٰ ؑ کی مانند نہیں ہو سکتے کیونکہ عیسائی نقطہ نگاہ سے انہوں نے شریعت کو لعنت قرار دے دیا تھا اور خود بھی لعنتی ہو گئے تھے.پھر اس پیشگوئی میں لکھا ہے کہ وہ نبی تیرے بھائیوں میں سے ہو گا.مگر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو داؤد کی نسل سے بتاتی ہے.اگر اس پیشگوئی کو حضرت مسیح ؑ پر چسپاں کیا جائے تو لازماً اُن کا حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوناغلط قرار پاتا ہے.حالانکہ مسیحی لوگ نہیں کہہ سکتے کہ انجیل نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے.اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے نہ کہ بنی اسمٰعیل میں سے.پس تیرے بھائیوں سے لازماً بنی اسرائیل مراد نہیں ہو سکتے.بلکہ اُن کے بھائی بنی اسمٰعیل ہی مراد ہیں.پھر اگر اس سے حضرت مسیح علیہ السلام مراد ہوتے تو وہ اپنے آپ کو اس کا مصداق بھی قرار دیتے اور دعویٰ کرتے کہ میں مثیل موسیٰ ؑ ہوں.مگر انجیل کو دیکھنے سے یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ حضرت عیسیٰ ؑ نے کبھی مثیل موسیٰ ؑ ہونے کا دعویٰ کیا ہو.لیکن قرآن کریم میں یہ دعویٰ موجود ہے.جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا١ۙ۬ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا(المزّمل: ۱۶) یعنی اے لوگو! ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر نگران ہے بالکل اُسی طرح جس طرح کہ فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا.یہ مثیل موسیٰ ہونے کا دعویٰ ہے.اِسی طرح سورۂ احقاف میں بھی مثیل کا لفظ پا یا جاتا ہے.جیسا کہ فرماتا ہے.قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهٖ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.(الاحقاف: ۱۱)یعنی کہہ دے کہ اے لوگو( جو قرآن کریم پر غور کرنا بھی پسند نہیں کرتے ) بتاؤ تو سہی اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو اور تم نے اس کا انکار بلا سوچے سمجھے کر دیا (تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا )اور پھر بنی اسرائیل میں سے ایک شخص (موسیٰ ؑ )اپنے ایک مثیل کی گواہی بھی دے چکا ہے.پس وہ تو اُس پر ایمان لے
Page 291
آیا.مگر تم لوگوں نے تکبر کیا.یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی کامیابی کا منہ نہیں دکھاتا.یہ اُسی پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے.جو حضرت موسیٰ ؑ نے کی تھی.اس جگہ اس پیشگوئی کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے.اور بتایا گیا ہے.کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثیل مو سیٰ ؑ ہیں.اور موسیٰ ؑ تو پیشگوئی کر کے اِس آنے والے نبی پر ایمان لے آیا.مگر تم نے انکار کر دیا اور تکبر سے کام لیا.غرض اس آیت میں عَلٰی مِثْلِہٖ کی پیشگوئی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں کیا گیا ہے.مگر حضرت عیسیٰ ؑ نے کہیں اسے اپنے اوپر چسپاں نہیں کیا.اس سے بڑھ کر ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت مسیح ؑ نے خود مثیل موسیٰ ؑ ہونے سے انکار کیا ہے اور اُن کا یہ انکار کتاب اعمال باب ۳آیت ۱۹تا ۲۶ میں درج ہے.لکھا ہے :.’’پس توبہ کرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں تاکہ خدا وندکے حضور سے تازگی بخش ایّام آویں.اور یسوع مسیح کو پھر بھیجے.جس کی منادی تم لوگوں میں آگے سے ہوئی.ضرور ہے کہ آسمان اُسے لئے رہے اُس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں.کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لئے ایک نبی میری مانند اٹھا وے گا.جو کچھ وہ تمہیں کہے اُس کی سب سنو.اور ایسا ہو گا کہ ہر نفس جو اس نبی کی نہ سُنے وہ قوم سے نیست کیا جائے گا.بلکہ سب نبیوں نے سموایل سے لے کے پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دنوں کی خبر دی ہے.تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے ہو جو خدا نے باپ دادوں سے باندھا ہے جب ابراہام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں گے.تمہارے پاس خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اُٹھا کے پہلے بھیجا کہ تم میں سے ہر ایک کو اُس کی بدیوں سے پھیر کے برکت دے.‘‘ اِس حوالہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس وقت تک نہیں آسکتے جب تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں پوری نہ ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھیں.اور آیت ۲۰ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مثیل موسیٰ ؑمسیح کی پہلی بعثت کے بعد اور دوسری بعثت سے پہلے آئے گا گویا اس جگہ اُن کی دو ۲ بعثتوں کا ذکر ہے.جن میں سے پہلی بعثت مثیل موسیٰ سے پہلے ہے اور دوسری بعثت مثیل موسیٰ کے بعد ہے.پس انجیل مثیلِ موسیٰ ؑ کی پیشگوئی حضرت مسیح علیہ السلام کی دو بعثتوں کے درمیان بتاتی ہے.حضرت مسیح علیہ السلام کا پہلا نزول مثیلِ موسیٰ ؑسے پہلے ہوا.اور
Page 292
دوسرا نزول اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام پیشگوئیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مثیل کے متعلق بیان فرمائی تھیں.پوری نہ ہو جائیں.اِسی طرح استثنا باب ۳۳ آیت ۲ میں بھی ایک پیشگوئی بیان کی گئی ہے جو یہ ہے.’’اور اُس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر طلوع ہوا.فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا.دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا.اور اُس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت اُن کے لیے تھی.‘‘ اِس میں آنے والے موعود کے متعلق کئی باتیں بیان کی گئی ہیں.اوّل یہ کہ وہ فاران کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوگا اور فاران کا پہاڑ مکہ کے علاقہ میں ہی ہے.دوسرے یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئیگا.اس جگہ دس ہزار قدوسیوں سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر دس ہزار صحابہؓ کاموجود ہونا ہے.اتنی بڑی تعداد کسی اور نبی کے ساتھ ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوئی.اور پھر صحابہؓ کے قدوسی ہونے کا ثبوت بھی قرآن کریم سے ملتا ہے.فرماتا ہے.رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ(التوبة:۱۰۰) کہ اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے.حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ صرف بارہ حواری تھے.مگر اُن میں سے بھی ایک نے تو تیس روپے لے کر حضرت مسیح ؑ کو گرفتار کرادیا.اور دوسرے نے آپ پر لعنت ڈالی اور باقی سب گرفتاری کے وقت آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ایسے جاں نثار صحابہؓ بخشے جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا اور اپنی جانیں قربان کر کے آپ کی حفاظت کی.تیسری علامت یہ بتائی گئی تھی کہ اُس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت ہو گی.اگر مثیل موسیٰ سے مراد اس جگہ حضرت مسیح علیہ السلام سمجھے جائیں تو یہ پیشگوئی غلط ٹھہرتی ہے کیونکہ مسیح ؑ کے پاس کوئی نئی شریعت نہیں تھی.اس جگہ قرآنی شریعت کو آتشی شریعت اِس لئے کہا گیا ہے کہ آتش کے دو۲ فائدے ہوتے ہیں.اوّل جلانا دوسرے ُنور دینا.گرم پانی یا گرم لوہا دوسری چیز کو جلا توسکتا ہے مگر وہ کسی کو نور نہیں دے سکتا.مگر آگ جلانے کے علاوہ نور بھی دیتی ہے.پس آتشی شریعت کہہ کر بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی شریعت ہو گی جو دو۲ کام کرے گی.اُس میں ایک طرف تو نار ہو گی اور دوسری طرف نو ر ہو گا.وہ ایک طرف تو تمام گندی اور بُری باتوں کو جلا کر راکھ کر دیگی اور دوسری طرف لوگ اُس سے نور حاصل کریںگے.غرض فاران سے دس ہزار قدوسیوں سمیت ایک الٰہی جلوہ کے ظہور کا وعدہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 293
کے ذریعہ پورا ہوا.فتح مکہ کے وقت آپ کے ساتھ دس ہزار قدوسی بھی تھے.اور پھر موسیٰ ؑکے بعد شریعت لانے کا دعویٰ بھی آپ کے سوا اور کسی نبی نے نہیں کیا.اِن دو۲ پیشگوئیوں کے علاوہ اَور بھی بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپاں ہوتی ہیں.دیکھو یسعیاہ باب۸ آیت ۱۴ تا ۱۷ وباب۹ آیت۱۳، ۱۷ وباب۲۸ آیت۹تا۱۳ وباب۳۵ آیت۳ تا۸ وباب ۴۰ آیت۹تا۱۲، وباب۴۲ و ۴۹ آیت ۵ تا۸ وباب۶۲ آیت۲ تا۴.نیز دیکھو دانیال باب ۷ و غزل الغزلات باب۵ آیت ۱۰تا۱۶ ومتی باب۲۱ آیت ۴۲ تا ۴۴.غرض فرمایا کہ ایک طرف تو یہ تعلیم حق پر مشتمل ہے اور دوسری طرف اس کے ماننے سے گزشتہ الہامی کتابوں کی پیشگوئیوں کی تصدیق ہو جاتی ہے.اگر وہ اس کا انکار کریںگے تو ان کو اپنی کتابوں کی بھی بہت سی باتیں جھوٹی ماننی پڑیں گی.اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس تعلیم کی صداقت منوانے کے لئے تین دلائل دیئے ہیں.اوّل یہ کہ یہ تعلیم خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے.دوم دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ ضرور دنیا میں قائم ہو کر رہے گی.سو م یہ تعلیم تمہاری اپنی کتابوں کی پیشگوئیوں کو جو آنیوالے موعود اور قرآن کریم کے متعلق ہیں پورا کرتی ہے.اگر تم اِس کا انکار کرتے ہو تو تمہیں اپنی کتابوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا.اور تم ان پر قائم نہیں رہ سکو گے.چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل یہود آپ کے منتظر تھے.اور اپنے بچوں کے نام تک محمد رکھا کرتے تھے.اور اس لئے رکھتے تھے کہ شاید وہ نبی ہم میں ہی پیدا ہو جائے.(اُسد الغابۃ محمد بن احیحۃؓ) لیکن جب وہ آگیا تو اُس کا انکار کر دیا.اور کہنے لگے کہ وہ بنی اسمٰعیل سے کس طرح آسکتا تھا.اُس نے تو ہماری طاقت کو بڑھانا تھا.عیسائی کہنے لگ گئے کہ اس سے مراد کلیسیا کی طاقت تھی.اسی طرح اور مختلف قسم کی تاویلیں کرنے لگ گئے.حالانکہ اگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو یقیناً ان کی طاقت بڑھ جاتی اور وہ تباہی سے بچ جاتے.فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ اگر ہم میں سے نبی آتا تو ہم اسے ضرور مان لیتے تو تم یہ بتائو کہ تم اُن انبیاء کو جو تمہاری قوم میں سے آئے تھے قتل کرنے کے کیوں درپے رہے؟اگر تم میں ایسی ہی شرافت پائی جاتی ہے.اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو بتائو کہ تم اُن پر کیوں ایمان نہ لائے اور ان کا مقابلہ کیوں کرتے رہے.پس یہ غلط ہے کہ جو کلام اسرائیلی نبی پر نازل ہو اُسے تم مان لیتے ہو.بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی خرابی کی وجہ سے انسان حق کا انکار کیا کرتا ہے.اور تم بھی اسی وجہ سے اس کلام کا انکار کر
Page 294
رہے ہو.یہ محض تمہارے نفس کا ایک دھوکا ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی نبی ہوتاتو تم اُسے ضرور مان لیتے.تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم ہمیشہ انبیاء کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہو.چنانچہ یہود کی اِس دیرینہ عادت کا حضرت مسیحؑ نے بھی ان الفاظ میں نوحہ کیا ہے کہ ’’اے یروشلم اے یروشلم جو نبیوں کو مارڈالتی اور انہیں جو تجھ پاس بھیجے گئے پتھرائو کرتی ہے.‘‘ (متی باب۲۳ آیت ۳۷) وَ لَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ اور موسیٰ تمہارے پاس یقیناً کھلے کھلے نشانات لے کر آیا تھا.پھر (بھی) تم نے اس کے (پہاڑ پر جانے کے) بعدظلم مِنْۢ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ۰۰۹۳ کرتے ہوئے (خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر) بچھڑے کو( معبود) بنا لیا تھا.تفسیر.فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس قول کا اجمالی جواب دیا تھا کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اُسے مان لیتے.اور فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے اِس قول میں سچے ہوتے تو اِس سے قبل بھی تم میں انبیاء آتے رہے ہیں تم ان کا مقابلہ کیوں کرتے رہے پس تمہارا یہ کہنا کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اِسے مان لیتے بالکل غلط ہے.اب اسی بات کا اللہ تعالیٰ اس جگہ مزید تشریح کے ساتھ جواب دیتا ہے.فرماتا ہے کہ تم حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو.اور تم نے اُس کے ساتھ بینات اورکھلے کھلے دلائل بھی دیکھے.مگر جب وہ طُور پر خدا سے برکات لینے گئے تو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اُس کی پرستش شروع کر دی.اب تم یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اگر یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو ہم اسے مان لیتے.تم نے اس نبی کے ساتھ جس پر تمہیں بڑا ناز ہے جب ایسا سلوک کیا تو اب تم سے یہ کیسے اُمید کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو تم اسے ضرور مان لیتے.یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بَیِّنٰت کا لفظ رکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی یہی لفظ استعمال فرمایا ہے.عیسائی لوگ بیّنات سے اُن کی ابنیت اور الوہیت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں.حالانکہ اگر اُن کا یہ استدلال درست ہو تو پھر انہیں حضرت موسیٰ ؑ کو بھی خدا کہنا چاہیے.مگر اُن کے متعلق وہ ایسا نہیں کہتے.پس ان کا
Page 295
صرف بیّنٰت سے حضرت مسیح ؑ کی ابنیت یا الوہیت کا استدلال کرنا غلط ہے.وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ.حقوق کا تلف کرنا دو۲ قسم کا ہوتا ہے.اوّل خدا تعالیٰ کے حقوق کو تلف کرنا.دوم بندوں کے حقوق کو تلف کرنا.اَنْتُمْ ظٰلِمُوْن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تلف کئے جانے کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ تم مشرک ہو جو میرے حقوق کو تلف کرتے ہو.ظالم کا لفظ مشرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے.کیونکہ ظُلم کے لغوی معنے وَضْعُ الشَّیْ ءِ فِیْ غَیْرِ مَحَلِّہٖ کے ہیںیعنی کسی چیز کو اُس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ رکھنا.چونکہ مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی صفات دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے اس لئے اُس پر ظالم کا لفظ اطلاق پاتا ہے.وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ١ؕ خُذُوْا اور (اس وقت کو بھی یاد کرو ) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا تھا(یہ کہتے ہوئےکہ)جو مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اسْمَعُوْا١ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا١ۗ وَ کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس (یعنی اللہ) کی اطاعت کرو.اس پر(تم میں سے جو لوگ اس اُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ١ؕ قُلْ بِئْسَمَا وقت ہمارے مخاطب تھے ) انہوں نے کہا تھا کہ (بہت اچھا) ہم نے سن لیا اور (ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیںکہ) ہم نے يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۰۰۹۴ (اس حکم کے)نہ ماننے کا فیصلہ کرلیا ہے اور ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں بچھڑا(یعنی اس کی محبت کا جذبہ) گھر کر گیا.تو (ان سے )کہہ کہ اگر تم (جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو ) مومن ہو تو وہ کام جس کا تمہیںتمہارا ایمان حکم دیتا ہے بہت برا ہے.حَلّ لُغَات.اِسْمَعُوْا.سَمِعَ لَہٗ کے معنے ہیں اَطَاعَہٗ اُس کی اطاعت کی.پس اِسْمَعُوْا کے معنے ہیں اطاعت کرو.اصل میں یہ اِسْمَعُوْا لَنَا ہے.یعنی جس طرح ہم نے کہا ہے اُس طرح کرو.مگر صلہ کو مخدوف کر دیا گیا ہے.اگر اس کے معنے سُننے کے کئے جائیں تو پھر اس لفظ کا استعمال لغو ہو جاتا ہے.کیونکہ اُن سے پہلے ایک عہدلے لیا گیا تھا اور عہد لے لینے کے بعد اُس کے سُننے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا.پس اس کے معنے اطاعت کرنے کے
Page 296
صرف بیّنٰت سے حضرت مسیح ؑ کی ابنیت یا الوہیت کا استدلال کرنا غلط ہے.وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ.حقوق کا تلف کرنا دو۲ قسم کا ہوتا ہے.اوّل خدا تعالیٰ کے حقوق کو تلف کرنا.دوم بندوں کے حقوق کو تلف کرنا.اَنْتُمْ ظٰلِمُوْن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تلف کئے جانے کی طرف توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ تم مشرک ہو جو میرے حقوق کو تلف کرتے ہو.ظالم کا لفظ مشرک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے.کیونکہ ظُلم کے لغوی معنے وَضْعُ الشَّیْ ءِ فِیْ غَیْرِ مَحَلِّہٖ کے ہیںیعنی کسی چیز کو اُس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ رکھنا.چونکہ مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی صفات دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے اس لئے اُس پر ظالم کا لفظ اطلاق پاتا ہے.وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ١ؕ خُذُوْا اور (اس وقت کو بھی یاد کرو ) جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا تھا(یہ کہتے ہوئےکہ)جو مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّ اسْمَعُوْا١ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا١ۗ وَ کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور اس (یعنی اللہ) کی اطاعت کرو.اس پر(تم میں سے جو لوگ اس اُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ١ؕ قُلْ بِئْسَمَا وقت ہمارے مخاطب تھے ) انہوں نے کہا تھا کہ (بہت اچھا) ہم نے سن لیا اور (ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیںکہ) ہم نے يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۰۰۹۴ (اس حکم کے)نہ ماننے کا فیصلہ کرلیا ہے اور ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں بچھڑا(یعنی اس کی محبت کا جذبہ) گھر کر گیا.تو (ان سے )کہہ کہ اگر تم (جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو ) مومن ہو تو وہ کام جس کا تمہیںتمہارا ایمان حکم دیتا ہے بہت برا ہے.حَلّ لُغَات.اِسْمَعُوْا.سَمِعَ لَہٗ کے معنے ہیں اَطَاعَہٗ اُس کی اطاعت کی.پس اِسْمَعُوْا کے معنے ہیں اطاعت کرو.اصل میں یہ اِسْمَعُوْا لَنَا ہے.یعنی جس طرح ہم نے کہا ہے اُس طرح کرو.مگر صلہ کو مخدوف کر دیا گیا ہے.اگر اس کے معنے سُننے کے کئے جائیں تو پھر اس لفظ کا استعمال لغو ہو جاتا ہے.کیونکہ اُن سے پہلے ایک عہدلے لیا گیا تھا اور عہد لے لینے کے بعد اُس کے سُننے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا.پس اس کے معنے اطاعت کرنے کے ہی ہیں.اُشْرِبُوا.اُشْرِبَ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے.عربی زبان کا محاورہ ہے اُشْرِبَ فُـلَانٌ حُبَّ فُـلَانٍ (اقرب) کہ فلاں شخص کی محبت دوسرے کے دل میں رچ گئی ہے.یہ لفظ ہمیشہ مجہول استعمال ہوتا ہے.اور اس سے پلانا نہیں بلکہ ملانا مراد ہوتا ہے.پس مطلب یہ ہے کہ بچھڑے کی محبت اُن کے ذرّہ ذرّہ میں رَچ گئی.اصل میں اس سے مائع کا جامد چیزوں میں ملانا مراد ہوتا تھا.چنانچہ’’بحرمحیط‘‘ میں لکھا ہے.وَالْاِ شْرَابُ مُخَالَطَۃُ الْمَائِعِ الْجَامِدِ وَتَوَسَّعَ فِیْہِ حَتّٰی صَارَفِی اللَّوْ نَیْنِ قَالُوْا وَ اَشْرَبْتُ الْبِیَاضَ حُمْرَۃً اَیْ خَلَطْتُھَا بِالْحُمْرَۃِ.یعنی اِشْرَابٌکسی مائع چیز کو جامد کے ساتھ ملانے کو کہتے ہیں.پھر اس کا استعمال اس قدر وسیع ہو گیا کہ یہ رنگوں کے آپس میں ملانے پر بھی بولا جانے لگا.چنانچہ اگر یہ کہنا ہو کہ میں نے سفیدی کو سُرخی میں ملا دیا.تو اُس وقت اِشْرَابٌ کا لفظ استعمال کرتے ہیں.اسی وسعت کے ماتحت یہ لفظ محبت کے دل میں گھر کرجانے پر بھی استعمال ہوتا ہے.چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے ؎ اِذَا مَا الْقَلْبُ اُشْرِبَ حُبَّ شَیْ ءٍ فَـلَا تَأْمَلْ لَہٗ عَنْہُ انْصِرَافًا یعنی جب کسی کے دل میں کسی کی محبت سرایت کر جاتی ہے تو اُس کے بعد یہ اُمید رکھنا کہ وہ محبت اُس سے جاتی رہے گی نا ممکن ہے.تفسیر.وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ.اس میں یہودکی عہد شکنی کی ایک اور مثال بیان کی ہے.فرماتا ہے تم اُس وقت کو بھی یا د کرو جب ہم نے موسیٰ ؑکے زمانہ میں تم سے ایک عہد لیا.اور عہد بھی ایسی حالت میں لیا جبکہ تم طور کے دامن میں کھڑے تھے جو کہ ایک مقدس مقام تھا مگر پھر بھی تم نے بد عہدی سے کام لیا اور طور کی تقدیس اور اس کی حرمت کا بھی خیال نہ رکھا.درحقیقت کسی مقدس مقام میں کھڑے ہو کر جو عہد کیا جاتا ہے اُسے باقی عہدو ں پر ایک نمایاں فوقیت حاصل ہوتی ہے.قرآن کریم نے بھی بعض قَسموں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ نماز کے بعد لی جائیں.کیونکہ ایسے موقع پر لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے لبریز ہوتے ہیں.یہ عہد کیا تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا ؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا ہے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اِسے مضبوطی سے پکڑو اور ہماری اطاعت کرو.مگر انہوں نے بجائے اطاعت کرنے کے کہا کہ ہم نے بات تو سن لی ہے مگر ہم یہ بھی کہے بغیرنہیں رہ سکتے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں گے.یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنی زبانوں سے ہی یہ الفاظ کہے ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اُن کی عملی نافرمانی کا اِن الفاظ میں اظہار کیا گیا ہو.یعنی اُن کے اندر روحانی لحاظ سے ایسا بگاڑ تھا.کہ وہ اِدھر بات سنتے اور اُدھر
Page 297
اس کی نافرمانی شروع کر دیتے.عربی زبان میں قَالَ کا لفظ کبھی زبانی قول کی بجائے عملی حالت کے اظہار کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے.جیسے کہتے ہیں.اِمْتَـلَأَ الْحَوْ ضُ وَقَالَ قَطْنِیْ.یعنی حوض بھر گیا اور اُس نے بزبانِ حال کہا کہ اب مجھ میں اور گنجائش نہیں.اِسی طرح یہاں بھی سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَاسے یہ مراد ہو سکتی ہے.کہ انہوں نے عملاً اس کی اطاعت سے انکار کر دیا.لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں انہوں نے سَمِعْنَا بھی کہا ہو.اور عَصَیْنَا بھی کہا ہو.کیونکہ انسان کسی بات کادو طرح جواب دیا کرتا ہے.ایک زبان سے اور دوسرے دل سے.پس اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کی زبانیں سَمِعْنَا کہہ رہی تھیں اور ان کے دل عَصَیْنَا کہہ رہے تھے.زبانیں تو کہتی تھیں کہ بس حضور یہی صحیح ہے گو یا وہ فرمانبرداری کا اقرار کر رہی تھیں مگر اُن کے دل نافرمانی کر رہے تھے.اور انکار پر مصر تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعلیم قابلِ عمل نہیں ہو سکتی.وَ اُشْرِبُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ.اس واقعہ کا ذکر خروج باب ۳۲ آیت ۲۰ میں اِس طرح آتا ہے کہ ’’اس نے اس بچھڑے کو جسے انہوں نے بنایا تھا لیا.اور اُس کو آگ سے جلایا اور اُس کو پانی پر چھڑک کر بنی اسرائیل کو پلایا‘‘.مگر قرآن کریم اِسے ردّ کرتا ہے.کیونکہ سونا نہ جل سکتا ہے اور نہ پانی میں حل ہو سکتا ہے.اس جگہ عجل سے مراد حُبُّ الْعِجْلِ ہے.یعنی اُن کے دلوں میں اُس کی محبت گھر کر گئی تھی.قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ.فرماتا ہے اگر تم واقعہ میں ایمان لانے والے ہوتے.تو کیا تمہارے ایمان تمہیں اس بات کی اجازت دے سکتے تھے کہ جب موسیٰ ؑ چند دنوں کے لئے باہر جاتے تو تم بُت پرستی شروع کر دیتے.پھر تو اس ایمان سے کفر ہی بہتر ہے.یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ’’بعد ازخدا بعشق محمدؐ مخمرّم گر کفرایں بود بخدا سخت کافرم‘‘ (ازالہ اوہام، روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۱۸۵) یعنی مجھ میں دو چیزوں کا عشق پایا جاتا ہے ایک اللہ کا اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.اگر تم اس وجہ سے مجھے کافر ٹھہراتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اس امر کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں بڑا سخت کافر ہوں.اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر تو تمہارا وہ ایمان تمہیں بہت برُا حکم دیتا ہے کیونکہ تم ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کرتے آئے ہو اور نبیوں کی مخالفت خواہ زبان سے ہو خواہ اعمال سے کبھی نیک نتائج پیدا نہیں کرتی.پھر اس کے ہوتے ہوئے تم اپنے آپ کو ایماندار اور
Page 298
مومن کیسے کہتے ہو.اگر اس کا نام تم ایمان کی بجائے انکار رکھو تو بہتر ہے.کیونکہ ایمان اور نبیوں کی مخالفت دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے.قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ تو (ان سے ) کہہ کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر (باقی) لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لئے ہے دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۰۰۹۵ تو اگر تم(اس دعویٰ میں) سچے ہو تو موت کی خواہش کرو.تفسیر.جو قوم اپنے اندر نبوت کو محدود کرتی ہے وہ لازماً نجات کو بھی محدود قرار دینے پر مجبور ہوتی ہے.چونکہ یہود کے اندر یہ خیال راسخ ہو چکا تھا کہ انبیاء صرف بنی اسرائیل میں ہی آسکتے ہیں.اس لئے لازماً اُن کے اندر یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ اگلے جہان کے انعامات کے بھی وہی حقدار ہیں.اور نجات صرف انہی کا حق ہے.اِن کے علاوہ اور کوئی قوم نجات حاصل نہیں کر سکتی.یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے نتائج کے لحاظ سے نہایت خطرناک ہے.مگر افسوس ہے کہ قرآن مجید سے قبل اس حقیقت کو اور کسی نے نہیں سمجھا.حالانکہ یہ ایسی غیر معقول بات ہے جسے کوئی عقلِ سلیم رکھنے والا انسان ایک منٹ کے لئے بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا.پھر یہ خیال صرف یہود ہی کا نہ تھا بلکہ اس وقت بعض اور اقوام میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی.چنانچہ ہندو قوم کو دیکھ لو.وہ بھی نجات صرف اپنے اندر محدود قرار دیتی ہے.کسی اَورکو نجات یا فتہ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتی.عیسائیوں نے بے شک آج کل اپنے مذہب کی تبلیغ عام کر دی ہے اور وہ کہتے ہیں.کہ جو بھی مسیحؑ کے کفارہ پر ایمان لے آئے وہ نجات پا سکتا ہے.مگر بعثت مسیحؑ سے پہلے وہ بھی نجات کو محدود قرار دیتے رہے ہیں اور اب بھی وہ اگر ساری دنیا کو تبلیغ کر رہے ہیں تو حضرت مسیحؑ کی تعلیم کے مطابق نہیں کر رہے.بلکہ اس کی تعلیم کو پس پُشت ڈال کر کررہے ہیں ورنہ مسیح نے توخود کہا تھا کہ ’’ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا.‘‘ (متی باب ۱۵ آیت ۲۴) اِسی طرح انہوں نے ایک طالب ہدایت عورت کو جوکہ اسرائیلی نہ تھی بلکہ کنعان کی رہنے والی تھی.صاف طور
Page 299
پر کہا کہ ’’ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کے آگے پھینک دیویں.‘‘ (متی باب ۱۵ آیت ۲۶) پھر حواریوں کا بھی یہی طرز عمل رہا.کہ وہ غیر اقوام میں انجیل کی منادی کرنا ناجائز سمجھتے تھے.چنانچہ اعمال میں لکھا ہے کہ ’’ وے جو اس جورو جفا سے جو کچھ استفنس کے سبب برپا ہوئی تتر بتر ہو گئے تھے پھرتے پھرتے فینیکے وکپرس اور انطاکیہ میں پہنچے مگر یہودیوں کے سوا کسی کو کلام نہ سُناتے تھے.‘‘ (اعمال باب ۱۱ آیت ۱۹) اِسی طرح جب حواریوں نے سنا کہ پطرس نے ایک جگہ غیر قوموں میں انجیل کی منادی کی ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے.’’اور جب پطر س یروشلم میں آیا تو مختون اُس سے یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ تو نا مختونوں کے پاس گیا اوراُن کے ساتھ کھانا کھایا‘‘.(اعمال باب ۱۱ آیت۲،۳) غرض مسیحیت کی عام تبلیغ انا جیل کے نقطہ نگاہ سے بالکل ناجائز ہے.اور جب مسیحیت کا دائرہ بھی ایک خاص طبقہ تک محدود ہے تو لازماً اُن کے نزدیک بھی نجات اُنہی لوگوں کےلئے مخصوص ہے جو حضرت مسیح پر ایمان لاتے ہیں.لیکن اسلام بتاتا ہے کہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کہ نجات کسی خاص قوم میں محدود ہے.وہ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (الذّٰریٰت:۵۷) فرماکر نجات دُنیا کے ہر فرد کا حق قرار دیتا ہے.اور بتاتا ہے کہ انسان کی پیدائش ہی اِسی لئے ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بنے اور اُس کی صفات کا انعکاس اپنے آئینۂ قلب میںپیدا کرے.زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے دو دعوے بیان کئے ہیں.ایک یہ کہ جنت اُن کا حق ہے اور دوسرا یہ کہ جنت میں اُن کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا.اللہ تعالیٰ اس جگہ یہود کے اس عقیدہ کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حضور دار آخرت صرف تمہارے لئے مخصوص ہے اور تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت صرف تمہارے گھرانے کے لئے ہی مخصوص کر دی ہے اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں تو پھر آؤ اس جھگڑے کے تصفیہ کیلئے موت کی تمنا کرو.
Page 300
فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کے دو معنے ہیں.ایک یہ کہ تم مباہلہ کر لو.یعنی مسلمانوں کا دُعا سے مقابلہ کر کے دیکھ لو.اور کہو کہ الٰہی ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اُسے تباہ و برباد کر دے.اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک تم سچے ہوئے تو خدا تعالیٰ تمہیں بچا لے گااور مسلمانوں کو تباہ کر دے گا اور اگر مسلمان سچے ہوئے.تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا اور مسلمانوں کو بچالے گا اور اس طرح دنیا کو پتہ لگ جائے گا.کہ خدا تعالیٰ کس سے ناراض ہے اور کس سے خوش.اِس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف موت کا لفظ استعمال کیا ہے.مَوْتَکُمْ نہیں فرمایا.کیونکہ مباہلہ میں یہ شرط ہوتی ہے کہ دونوں فریق یہ دعا کریں کہ جھوٹے پر عذاب نازل ہو.اِس میں کسی فریق کی تعیین نہیں کی جاتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ میں بھی یہ الفاظ رکھے ہیںکہفَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ (آل عمران: ۶۲)یعنی ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں.پس فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کے یہ معنے ہیں.کہ اگر یہود حق پر ہیں.اور اگلے جہان میں خدا تعالیٰ کے انعامات کے وہی وارث ہیں تو اس بات کو ثابت کرنے کیلئے وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں یہ دعا کریں کہ الٰہی ہم میں سے جو فریق جھوٹا ہے اور جس سے تو ناراض ہے اُسے ہلاک اور برباد کردے.اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک واقع میں یہود پسندیدہ ہیں.اور مسلمان قابل سرزنش ہیں.تو مسلمان ہلاک ہو جائیں گے اور یہود کو سر فرازی حاصل ہوجائے گی.اور اس طرح دنیا کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع مل جائے گا کہ آخرت کے متعلق کس قوم کا دعویٰ سچا ہے.کیونکہ آخرت کے متعلق مختلف مذاہب کے دعوؤں کی صداقت پر کھنے کا سوائے اِس کے اور کو ئی ذریعہ نہیں کہ اِس دنیا میں ہی آسمانی تائیدات سچے مذہب کے اِدَّعَا کو ثابت کردیں.اور دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ خدا کس کے ساتھ ہے.فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کے دوسرے معنے یہ ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تم ہی نجات یافتہ ہو تو اِس دعویٰ کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمہارے متعلق یہ سمجھا جائے کہ تمہارا ہرفرد پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر قائم ہے.اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار اور اُس کی برکات کا تجلّی گاہ ہے.ایسی صورت میں تم خدا تعالیٰ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کیوں نہیں کرتے اور اپنی سفلی زندگی پر ایک موت واردکیوں نہیں کرتے.جو قوم اکیلی جنت کی مستحق ہو اُسے اس دنیا سے محبت کیوں ہو.اُسے تو رضاءِ الٰہی کے کاموں میں اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ نے بہترین جہان اس کے لئے مخصوص کر دیا ہے.پس فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَکے دوسرے معنے یہ ہیں کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دو.اور اس راہ میں جس قدر بھی تکالیف تمہیں برداشت کرنی پڑیں اُن کو برداشت کرو.اور ہر قسم کی جانی اور مالی قربانیوں میں حصّہ لے کرثابت کر دو کہ تم نے ایک بے جان چیز کی طرح اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر رکھا ہے.اگر تم ایسا کرو تو یہ سمجھ لیا جائے گا کہ تمہارا یہ دعویٰ درست ہے کہ تمہارے سوا اور کسی کے لئے
Page 301
اُخروی انعامات مقدّر نہیں.مگر فرمایا.وَ لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ.وہ اس موت کو کبھی بھی اپنے اوپر وارد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عیاشیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت سے غافل ہیں.اِن میں اخلاص اور قربانی کی کوئی روح موجود نہیں.اور جنت کا اُن کےلئے مخصوص ہونا تو الگ رہا.اُن کو جنت کے ملنے کا بھی یقین نہیں.بلکہ اُس کے وجودپر بھی انہیں یقین نہیں کیونکہ دنیا کی محبت اُن کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے ہے اور یہ محبت اُن کے بعث بعد الموت پر عدم ایما ن کا ایک نمایاں ثبوت ہے.یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے.کہ قرآن کریم میںتو آیا ہے کہ یہود کہتے ہیں.لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَیَّامًا مَّعْدُوْدَۃً یعنی ہمیں دوزخ میں صرف چند دن کے لئےڈالا جائے گا.اور یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جنّت صرف ہمارا ہی حق ہے.اِن دونوں باتوں میں تو بہت بڑا اختلاف ہے.پھر بیک وقت دونوں باتیں اُن کی طرف کِس طرح منسوب ہو سکتی ہیں ؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہود کے دو۲ گروہ ہیں.اور ان دونوں کے الگ الگ عقیدے ہیں.ایک گروہ کا خیال تھا کہ ہم کچھ دن دوزخ میں رہ کر نکل آئیں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم دوزخ میں بالکل نہیں جائیں گے.پہلے اُس گروہ کا ذکر آچکا ہے جو صر ف گنتی کے چند دنوں کیلئے دوزخ میں ڈالے جانے کا قائل تھا.اب اللہ تعالیٰ اُس گروہ کا ذکر کرتا ہے جس کا یہ عقیدہ تھا کہ نجات صرف بنی اسرائیل سے مخصوص ہے اور نبوت بھی کسی اور قوم میں نہیں جا سکتی.اس گروہ کے متعلق یہود کی کتاب ایروبین طالمود میں لکھا ہے کہ گنہگار یہودی دوزخ کے دروازے تک لے جائے جائیں گے تو وہاں تو بہ کر لیں گے.اور وہاں سے بغیر سزا دئیے کے واپس کر دئیے جائیں گے.اور پھراُن کو جنت میں لے جایا جائے گا.(جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ (Gehenna) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود کا وہ گروہ جو کہتا ہے کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی.اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ دوسروں کے لئے ہرگز نجات نہیں وہ اگر اپنے اس عقیدہ میں سچے ہیں تو مسلمانوں سے مباہلہ کر لیںیا اپنے عمل سے خدا تعالیٰ کے لئےاپنے اوپر موت وارد کر کے اپنی پاکیزگیء ِ نفس اور بلندیٔ کردار کا ثبوت پیش کریں.حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے قبل تقریباً تمام مذاہب میں یہ تعلیم پائی جاتی تھی کہ نجات صرف اُنہی کا حق ہے.بلکہ ہندوؤں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو شودر وید سُن لے اُس کے کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈالا جائے.وہ کہتے تھے کہ یہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے.مگر ان کو کلام الٰہی سننے کا کوئی حق نہیں.بد ھ قوم میں دوسروں کی نسبت قومی احساس کم تھا اور ان کی تبلیغ عام تھی لیکن تبلیغ عام ہونے کے باوجود وہ نبوت کو عام نہیں سمجھتے تھے.بلکہ اُسے محدود قرار دیتے تھے.اِس لئے اُن کے نظریہ میں بھی وہ وسعت نہیں تھی جو اسلام نے پیش کی ہے.
Page 302
یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی تو وہی عقیدہ ہے جو یہود کا تھا کہ نبوت صرف ہم میں ہی رہے گی اور ہم ہی نجات کے مستحق ہیں.پھر مسلمانوں کو دوسروں پر کیا فضیلت حاصل ہوئی.اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان نہ تو ہر نام نہاد مسلمان کے لئے جنّت ضروری قرار دیتے ہیںاور نہ کسی خاص قوم کے آدمیوں کے سوا دوسروں کے لئے نجات کا دروازہ بند قرار دیتے ہیں.بلکہ وہ سب دنیا کے لئے اس کا دروازہ کھلا تسلیم کرتے ہیں.پس اسلام پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اُس نے بھی نجات اپنے پیروؤںکے لئے مخصوص کر لی ہے.اسلام تمام قوموں کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے اور دنیا کا ہر فرد اس کے پیغام کا مخاطب ہے.اگر بنی اسرائیل بھی اس نبی کو مان لیتے تو وہ اپنے اوپر نجات کا دروازہ کھول سکتے تھے.اِس طرح دوسری اقوام بھی اس نبی کو مان کر نجات پا سکتی ہیں.دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک بات بطور استحقاق ہوتی ہے.اور ایک بطور تَلطّف اور رحم کے ہوتی ہے.جو شخص سچی تعلیم کو ماننے والا ہو.ا س کاایک حق ہوتا ہے اور گو وہ حق اس کا ذاتی طور پر نہیں ہوتا مگر بہر حال خدا تعالیٰ نے اس کا ایک حق قائم کیا ہوتا ہے.اس نقطہ نگاہ سے جو شخص شریعت حقّہ اسلامیہ پر ایمان رکھے اس کےلئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اُسے نجات دے گا.یہ امر اس کے لئے استحقاق کے طور پر ہے اور اسی وجہ سے سچے مذہب کے تمام پیرو نجات حاصل کرنے کے مستحق ہوتے ہیں.لیکن دوسرے لوگ بطور تَلطّف اور رحم کے نجات حاصل کرتے ہیں.اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے.جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے.رَحْمَتِیْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف: ۱۵۷)کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے.اِس رحمت عام میں یہودی ، عیسائی اور ہندو وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں.اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ماتحت ہر شخص جنت میں جا سکتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے.اسلام پر اعتراض تب ہوتا جب اسلام میں دوسرے لوگ شامل نہ ہو سکتے.مگر جب اسلام نے ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں کے لئے اپنے دروازے کھول رکھے ہیںاور اُن کو دعوت دے دی ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا.اعتراض اُن مذاہب پر پڑتا ہے جنہوں نے نجات کا دروازہ دوسروں کے لئے بند کر دیا ہے اور انہیں اپنے اند ر شامل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی.بہر حال اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب نے نجات کو اپنے لئے مخصوص کیا ہوا ہے.صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اسے اپنے ساتھ مخصوص نہیں کرتا.کیونکہ تَلطّف کی نجات صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص نہیں بلکہ اس میں غیر مسلم بھی شامل ہو سکتے ہیں.مگر یہودی تعلیم کی رو سے کوئی غیریہودی نجات حاصل نہیں کر سکتا اور عیسائیوں کے نزدیک کوئی غیرعیسائی نجات نہیں پا سکتا.لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ جنت صرف مسلمان کہلانے پر ملتی ہے.بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان کہلا کر برُے کام کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو گا.اِسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو اور وہ
Page 304
اگر کوئی شخص سوال کرے کہ اگر اسلام قبول کئے بغیر بھی انسان کو نجات مل سکتی ہے.تو پھر وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران: ۸۶)کا کیا مطلب ہے ؟ تو اِسے یاد رکھنا چاہیے کہ اِس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات جو استحقاق کے طور پر ملتی ہے.وہ مسلمانوں کے سوا اور کسی کو نہیں مل سکتی.مگر جیسا کہ بتایا جا چکا ہے.یہ حق بھی وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے.ورنہ بندہ کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ذاتی حق نہیں.ہاں اللہ تعالیٰ نے خود بندے کا اپنے اوپر ایک حق قائم کر لیا ہے.اور خدا تعالیٰ کے مقرر کرنے کی وجہ سے بطور استحقاق نجات صرف مسلمانوں سے مخصوص ہے.اِن میں سے جو شخص بھی قرآن کریم پرعمل کرے گا نجات حاصل کرلے گا.لیکن دوسرے لوگ بطور رحم کے نجات حاصل کر سکتے ہیں.مثلاً اگر کوئی بچہ بہرہ یا پاگل اور معذور ہو تو اُسے دوبارہ موقع دیا جائے گا.اور یا پھر اس کے فطرتی ایمان کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گااور یہ دیکھا جائےگا کہ آیا اس نے اس ایمان کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں ورنہ اگر خد ا تعالیٰ کسی کو بخشنا چاہے تو ہم اُس کا ہاتھ نہیںپکڑ سکتے.وہ مالک ہے جسے چاہے نجات دے.وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص غیر اسلام کا ابتغاء کرتا ہے وہ عام قانون کے مطابق نجات نہیں پا سکتا.کیونکہ وہ خود اپنے لئے نجات کا دروازہ بند کرتا ہے اور استحقاق سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے.لیکن نجات کے اور بھی ذرائع ہیں.اگر ان کے ماتحت کوئی شخص آجائے تو یقیناً نجات پا جائے گا.وَ لَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ١ؕ اور (اے مسلمانو!یاد رکھوکہ) جو کچھ ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اس کے سبب سے وہ کبھی بھی اس (قسم کی موت) وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ۰۰۹۶ کی تمنّا نہیں کریں گے.اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے.تفسیر.تَمَنَّوُا الْمَوْتَ کے دو۲ معنوں کی رو سے اِس کے بھی دو معنے ہوں گے.اگر موت سے مباہلہ مراد لیا جائے تو اِس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ ہر گز مباہلہ نہیںکریںگے.اور ان کا یہ گریز اس امر کا ثبوت ہو گا کہ اُن کے دل جانتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی مرضی کے مطابق کام نہیں کیا.ورنہ وجہ کیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں.اُن کا پیچھے ہٹنا بتاتا ہے کہ انہیں اپنی بدیاں معلوم ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے مباہلہ کیا تو انہیں اپنے گناہوں کی سزا مل
Page 305
جائے گی.دوسرے معنے تَمَنَّوُا الْمَوْتَ کے یہ تھے کہ تم خدا کی رضاء کے لئے اپنے آپ کو فنا کرو اور اپنے اوپر وہ موت وارد کرو جو ابدی زندگی کا پہلا قدم ہے.اِس مفہوم کے لحاظ سے آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ وہ کبھی بھی اِس موت کو جس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حیات ابدی عطا کرتا ہے قبول نہیں کریں گے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اُن کی روحانیت مسخ ہو چکی ہے اور اب وہ ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اُن کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ خدا کے لئے اپنے آپ پر موت وارد کریں.گویااُن کی گردنوں میں جو گناہوں کے طوق و اغلال پڑے ہوئے ہیں اُن کی وجہ سے انہیں یہ توفیق ہی نہیں ملے گی کہ وہ یہ نمونہ دکھا سکیں.وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ میں بتایا کہ جُھوٹے کی یہ علامت ہے کہ وہ آنوں بہانوں سے مباہلہ کو ٹلاتا چلا جاتا ہے کبھی مقابلہ پر نہیں آتا.مگر کیا وہ اس طرح بچ جائیں گے؟ آخر ایک دن پکڑے جائیں گے.اور ان کا انجام لوگوں پر ظاہر کردے گا کہ کون ظالم تھا اور کون راستباز چنانچہ یہود پر جو تباہیاں آئیں.اُس نے اُن کے انجام کو ظاہر کر دیا.وَ لَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ١ۛۚ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اور تو یقیناً انہیں (بھی) اور بعض ان لوگوں کو (بھی ) جو مشرک ہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائے گا ان اَشْرَكُوْا١ۛۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ١ۚ وَ مَا هُوَ میں سے (ہر )ایک (یہی)چاہتا ہے کہ اسے ہزار سال کی عمر مل جائے حالانکہ یہ (امر ) یعنی اس کا (لمبی) عمر پانا اس بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُّعَمَّرَ١ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَؒ۰۰۹۷ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا.اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے.حَلّ لُغَات.یَوَدُّکے معنے پسند کرنے کے ہیں.مگر جب لَوْ اس کے بعد آئے تو اس کے معنے تمنا کرنے کے ہوتے ہیں.(المنجد) تفسیر.فرماتا ہے.یہ لوگ سب سے زیادہ اس بات کے حریص ہیں کہ زندہ رہیں.حتّٰی کہ مشرکوں سے
Page 306
بھی زیادہ حریص ہیں.گویا اَحْرَص ہونا یہود کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے.یوں مشرک بھی بڑے حریص ہوتے ہیں کیونکہ وہ قیامت کے منکر ہوتے ہیں.اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس قدر ہو سکے دنیا میں زندہ رہیں.مگر فرماتا ہے.یہ لوگ اِن سے بھی زیادہ حریص ہیں.دوسرے معنے یہ ہیں کہ ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے بعض کو تو دنیا کی زندگی کا زیادہ حریص پائے گا.گویا ان کی حرص پر زیادہ زور دینے کے لئے مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا کو اَلنَّاسسے علیحدہ کرلیا.جیسے کہتے ہیں جَآءَ قَوْمٌ وَزَیْدٌ وَ عَمْرٌو.قوم کے لوگ آئے اور زید اور عمرو بھی آگئے.حالانکہ زید اور عمرو بھی قوم میں شامل ہیں مگر ان کا نمایاں کرنے کے لئے الگ نام لے لیا گیا.مشرک دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک وہ جو قیامت کے منکر ہوتے ہیں اور اس جہان میں آرام سے رہتے ہیں.وہ طبعًا دنیوی زندگی کے بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں.دوسری قسم کے مشرک وہ ہوتے ہیں جو قیامت کے تو منکر ہوتے ہیں مگر اس جہان میں انہیں آرام نہیں ہوتا.اس قسم کے مشرک زندگی کے ختم ہونے کے متمنّی ہوتے ہیں تاکہ انہیں ان تکالیف سے نجات مل جائے.وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کا ختم ہو جانا ہی سُکھ کا موجب ہے.اس لئے فرمایا کہ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا.اِن مشرکوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو ہزار سالہ زندگی چاہتی ہے ورنہ سارے مشرک ایسے نہیں.اِس آیت سے نصِّ صَریح کے طور پر تو نہیں صرف ایک استنباط کے رنگ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآنی نظریہ کے مطابق انسان کی ہزار سالہ زندگی ایک بعید از قیاس امر ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کتاب’’ چشمۂ معرفت‘‘ لکھ رہے تھے تو آپ کا قاعدہ تھا کہ آپ بعض دفعہ اُس کے مضامین دوسروں کو بھی سُنادیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے حضرت نوح ؑ کی۹۵۰ سالہ عمر پر آریوں کے اعتراض کے بارہ میں فرمایا کہ ہم نے اس کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی عمر سے مراد اُس کی اپنی عمر نہیں ہوتی بلکہ اُس کی جماعت کی عمر ہوتی ہے.آپ یہ سُناہی رہے تھے کہ حضرت نانا جان میر ناصر نواب صاحب تشریف لے آئے.وہ کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے مگر لوگ نیچریّت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں.آپ نے فرمایا.ہوتے ہیں تو ہوں پھر کیا ہوا ہمیں تو جہاں بھی اسلام کی صداقت نظر آئے گی ہم اُسے پیش کریںگے خواہ کوئی اُس سے نیچریت کی طرف ہی کیوں نہ مائل ہو جائے.بہرحال قرآن مجید میں جہاں کسی نبی کی زیادہ عمر کا ذکر آتا ہے.وہاں ایک فرد کی عمر مُراد نہیں بلکہ اُس کی اُمت کی عمر مراد ہے.
Page 307
وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ میں ھُوَ کی ضمیراَحَدُھُمْ کی طرف جاتی ہے اور ترجمہ کے لحاظ سے یہ عبارت یُوں بنتی ہے کہ مَا اَحَدُھُمْ بِمُزَحْزِحِہٖ تَعْمِیْرُہٗ مِنَ الْعَذَابِ کہ اُن میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جسے زیادہ عمر کا دیا جانا عذاب سے بچا سکے.فرماتا ہے لمبی عمر کی خواہش کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا.کیونکہ آرام کی لمبی گھڑیا ں دُکھ کی ایک چھوٹی سی گھڑی کے مقابلہ میں بھی ہیچ ہو جاتی ہیں.اور راحت کی گھڑیوں پر غالب آجاتی ہے.پس لمبی عمر انہیں عذاب سے بچا کر کہاں لے جائے گی.اور ان کو اس سے کیا فائدہ ہو گا.یہ تو حماقت کی بات ہے.مگروہ اس میں اسی طرح مبتلا ہیں جس طرح وہ اپنی اس پہلی حماقت میں مبتلا تھے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو انعام نبوت حاصل نہیں ہو سکتا.اب بھی یہ احمق لوگ یہ خواہش تو نہیں کرتے کہ عذاب کو اُن سے ٹلا دیا جائے بلکہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ عذاب کچھ دیر پیچھے ہو جائے.حالانکہ اس سے انہیں کیا فائدہ ؟ اصل علاج تو یہ تھا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیتے جس نے اُن کے لئےنجات کا دروازہ کھولا ہوا ہے.مگر بجائے اِس کے کہ وہ اسلام قبول کرکے اس عذاب کو ٹلا دیں یہ اس کو شش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ پیچھے ہو جائے.حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس سے بچ جائیں اور خدا تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیں.اِس رکوع کی آیت نمبر ۸۸ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو بتایا تھا کہ دیکھو تم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک تمام انبیاء کی مخالفت کرتے آئے ہو اور گو اُن کی مخالفت تمہارے آباء نے کی مگر تم بھی اُس میں اس لئے شریک ہو کہ تمہاری اور اُن کی مخالفت کی وجہ ایک ہی ہے.یعنی اپنے منشاء کے خلاف نبی ءِ وقت کی تعلیم کاہونا.پس اگر ان کے وقت میں تم ہوتے تو اُس وقت بھی تم وہی کچھ کرتے جو اَب کررہے ہو.آیت ۸۹ میں یہود کا ایک قول نقل فرمایا کہ نبیوں کے جواب میں ایسے اقوال سے تم ان کی ہنسی اُڑایا کرتے یا اپنے تکبر کا اظہار کیا کرتے تھے.آیت ۹۰ میں بتایا کہ غضبِ الٰہی اور تمہاری آبائی عادت کا یہ نتیجہ ہے کہ جب وہ موعود رسول آیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے تو تم انکار کر بیٹھے.آیت ۹۱ میں اس کے انکار کی وجہ بتائی جو صرف یہ ہے کہ غیر قوم سے کیوں رسول آیا ؟ آیت ۹۲ میں ان کے تمردانہ انکار کا نقشہ کھینچا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو بغیر سوچے سمجھے اور دلائل پر غور کرنے کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو وہی مانیں گے جو بنی اسرائیل کے انبیاء پر نازل ہوا.حالانکہ یہ نبی بھی اُنہی انبیاءبنی اسرائیل کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہے.پھر اُن کے اس مقابلہ کو یاد دلا کر جو وہ انبیائے بنی اسرائیل کا وقتاً فو قتاً کرتے رہے ہیں ان کو نادم کیا گیا ہے.کہ تم نے اُن کے وقت میں اُن کو بھی نہیں مانا
Page 309
عبرانی میں خادم اور غلام کے معنے رکھتا ہے.اس کے یہ معنے عربی زبان میں بھی ملتے ہیں لیکن ایل کے معنوں میں عربی زبان اور عبرانی زبان میں بڑا فرق ہے.عبرانی میں عام طو رپر یہ لفظ خدا کیلئے آتا ہے.مگر اس کےیہ معنے عربی میں نہیں پائے جاتے.بلکہ ایل کا لفظ ہی عربی زبان میں نہیں آتا.لیکن تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں اٰئل کا لفظ آتا ہے.جو اٰلَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے.اور اٰلَ کے معنے ہیں.اُس نے تدبیر سے حکومت کی.چنانچہ اٰلَ اْلمَلِکُ رَعِیَّتَہٗ کے معنے ہوتے ہیں.سَا سَھُمْ بادشا ہ نے اپنی رعایا کی ضروریات کا انتظام کیا.اور اٰلَ عَلَی اْلقَوْمِ کے معنے ہیں.وَلِیَ وہ قوم کا بادشاہ بن گیا.غرض اٰلَ کے عربی زبان میں کئی معنے ہیں.ایک معنے اِس کے لوٹنے کے بھی ہیں.اس لحاظ سے آئل لوٹنے والے کو بھی کہتے ہیں.(اقرب ) پس آئل لوٹنے والے ، مدبر حاکم اور بادشاہ کو کہتے ہیں.اور یہ سب الفاظ خدا تعالیٰ پر چسپاں ہو سکتے ہیں.ان معانی کے لحاظ سے جبریلکے تین معنے ہوں گے (۱) بادشاہ کا بہادر اور اچھا خادم (۲)ایک مدّبر ہستی کا بہادر اور اچھا غلام (۳) اپنے بندوں کی طرف بار بار رحمت کے ساتھ لوٹنے والے خدا کا بہادر اور اچھا خادم.عبرانی زبان میں بھی ایل کے معنے آئل سے ملتے جلتے ہیں.کیونکہ عبرانی کے بعض ماہر علماء کہتے ہیں.کہ ایل کے معنے طاقتور کے ہیں.(انسائیکلو پیڈیا ببلیکا زیر لفظ EL )جو حاکم یا مدبّر سے ملتے ہیں.لیکن عبرانی کے بعض دوسرے ماہر کہتے ہیں.کہ اس لفظ کے معنے ہیں.’’وہ وجود جو سب انسانوںکا مرجع ہے‘‘.یہ اٰئل کے دوسرے معنی یعنی لَوٹنے والے سے کسی قدر فرق کے ساتھ ملتے ہیں.عربی زبان کو ملحوظ رکھتے ہوئے جبریلکے معنے ہیں بار بار لوٹنے والے یعنی تَوَّاب خدا کا خادم.یہ خدا تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ بار بار الہام نازل کرتا ہے اور بار بار اپنے بندوں کی طرف رجوع کرتا ہے.لیکن جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں عبرانی زبان کے ماہر کہتے ہیںکہ عبرانی میں ایلکے معنے ہیںوہ ذات جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں.اور جو سب انسانوں کا مرجع ہے.یہ معنے عربی زبان سے کسی قدر مختلف ہیں.گو جہاں تک َلوٹنے کا سوال ہے اس کا دونوں معنوں میں ذکر آتا ہے.صرف اس قدر فرق ہے کہ عبرانی نے اُسے مرجع بتایا ہے اور عربی نے راجع.یعنی عربی میں اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ خدا جو بندہ کے پشیمان ہونے پر بار بار اپنے فضل کے ساتھ اُس کی طرف رجوع کرتا ہے اور عبرانی میں اس کے معنے ہیں وہ ہستی جس کی طرف لوگ بار بار رجو ع کرتے ہیں.یہ تغیر ایسا ہی ہے.جیسے عبرانی میں ایلو ھیم جس کے معنے مضبوط اور طاقتور ہونے کے ہیں اس کے معنے مضبوط کے ہو گئے ہیں اور اب محاورہ میں یہ لفظ ہر اس وجود کیلئے استعمال کر لیتے ہیںجو مضبوط اور طاقتور ہو.پس جس طرح یہاں معنوں میں تغیر
Page 310
پیدا ہو گیا ہے اسی طرح اٰئل کے معنے َلوٹنے والے سے بدل کر ’’جس کی طرف لوٹا جائے ‘‘ہو گئے.اس کی زیادہ تر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہود خدا تعالیٰ کی تَوَّاب صفت کے قائل نہیں تھے اور وہ اس کے قائل ہو بھی نہیں سکتے تھے.کیونکہ جو قوم یہ سمجھتی ہو کہ خدا تعالیٰ پر ہمارا حق ہے وہ ہمیں بہر حال نجات دے گا.وہ خدا تعالیٰ کو تَوَّابکیسے مان سکتی ہے.وہ تو اُسے کبھی بھی تَوَّاب نہیں مانے گی.اُسے تَوَّاب وہی مان سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ اُس پر میرا کوئی حق نہیں.مگر یہود کا یہ عقیدہ نہ تھا.وہ خدا تعالیٰ پر اپنا حق جتاتے تھے.اسی لئے انہوں نے ایلکے معنے کر دئیے ’’وہ ہستی جس کی طرف لوگ لَوٹتے ہیں‘‘.نہ یہ کہ وہ خدا جو لوگوں کی طرف بار بار رحمت کے ساتھ لوٹتا ہے.یہی وجہ ہے کہ عبرانی زبان میں تَوَّابکے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان نہیں ہوئی.لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ اس کے اصل معنے لئے جائیں.یعنی بار بار لوٹنے والے خدا کا بہادر اور اچھا خادم یا ایک مدبّر ہستی کا بہادر اور اچھا خادم.تفسیر.قرآن کریم اور بائیبل دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ جبریل خدا تعالیٰ کے مقرب ملائکہ کا سردار ہے اور اس کا کام بندوں تک کلام الٰہی پہنچانا ہے.مگر یہود اپنے تنزل کے زمانہ میں جبریل کو لڑائی اور عذاب کا فرشتہ سمجھنے لگ گئے تھے.(انسائیکلوپیڈیا ببلیکا.زیر لفظ جبریل ) اور اسے اپنا دشمن تصور کرتے تھے.چنانچہ مسند احمد بن حنبل اور ابن کثیر کی روایت ہے کہ یہود جب مسلمانوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل اور براہین سنتے اور کوئی جواب نہ دے سکتے تو کہہ دیتے کہ اچھا ہمیں یہ بتاؤ.کہ اُن کی طرف وحی کون لاتا ہے ؟ اس کے جواب میں مسلمان کہتے کہ جبریل.اِس پر یہود پکار اُٹھتے کہ جِبْرِیْلُ ذَاکَ الَّذِیْ یَنْزِلُ بِا لْحَرْبِ وَالْقِتَالِ وَ اْلعَذَابِ عَدُوُّنَا.(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا بر حاشیہ فتح البیان) یعنی جبریل تو وہ فرشتہ ہے جو جنگ و جدال اور عذاب لے کر نازل ہوتا ہے اور ہمارا دشمن ہے اس لئے ہم یہ کلام نہیں مان سکتے.یہود میں یہ خیال زیادہ تر طالمودی روایات اور ٹار گم کی تفسیروں سے پھیلا ہے.ورنہ بائیبل جبریل کو کلام الٰہی لانے والا فرشتہ ہی قرار دیتی ہے چنانچہ دانیال باب ۸ آیت ۱۶، ۱۷ میں لکھا ہے.’’اور میں نے اُولائی میں سے آدمی کی آواز سُنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبریل اِس شخص کو اس رؤیا کے معنے سمجھا دے.چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اُس کے آنے سے میںڈر گیا اور منہ کے بل گرا.پر اُس نے مجھ سے کہا.اے آدم زاد سمجھ لے کہ یہ رؤیا آخری زمانہ کی بابت ہے.‘‘
Page 311
اسی طرح دانیال باب ۹ آیت ۲۱ میں لکھا ہے :.’’میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رؤیا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیاا ور شام کی قربانی گزراننے کے وقت کے قریب مجھے چھؤا اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کیں ‘‘.لوقا باب ۱ آیت ۱۹ میں بھی لکھا ہے :.’’فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا.میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں.‘‘ اِسی طرح لوقا باب ۱ آیت ۲۶ میں لکھا ہے.’’چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرہ تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا.‘‘ مگر بعد میں یہودی احادیث میں جبرائیل کو عذاب کا فرشتہ قرار دے دیا گیا اور میکا ئیل کو وحی الٰہی لانے والا فرشتہ سمجھا جانے لگا.دانیال نبی کے وقت تک وہ مانتے تھے کہ جبرائیل کلام الٰہی لانے والا فرشتہ ہے.اوردنیوی ترقیات کا تعلق میکا ئیل کے ساتھ ہے.لیکن رفتہ رفتہ وہ میکائیل کو کلام الٰہی لانے والا فرشتہ سمجھنے لگ گئے.اور جبرائیل جو کلام لاتا تھا وہ چونکہ نہ ماننے والوں کیلئے سزا کا بھی پیغام لاتا تھا اس لئے وہ اُسے نا پسند کرنے لگ گئے.یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ میں یہود کا یہ پختہ خیال ہو گیا کہ جبرائیل گرج اور عذاب کا فرشتہ ہے.(انسائیکلو پیڈیا ببلیکا زیر لفظ جبریل) معلوم ہوتا ہے کہ یہود چونکہ مغضوب قوم تھی.اور جو نبی بھی اُن کی طرف آتا وہ اُنہیں ڈراتا اور کہتا کہ تم تباہ ہو جائو گے.اس لئے وہ عذابوں کے پَے درپَے آنے کے سبب سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ جبرائیل اُن کا دشمن ہے.کیونکہ وہ جو کلام بھی لاتا ہے اُس میں عذاب ہی عذاب کی خبریں ہوتی ہیں.پس وہ جبریل سے عداوت رکھنے لگ گئے.وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس کے ماننے کی ضرورت نہیں.اصل فرشتہ میکائیل ہے جس کی لائی ہوئی وحی ماننے کے قابل ہے.وہ جبرائیل کو لڑائی اور جھگڑے پیدا کرنیوالا فرشتہ اس لئے کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ انبیاء کا انکارکرتے تھے.اور اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُن پر عذاب نازل کیا کرتا تھا.اِن عذابوں کو وہ جبرائیل کی طرف منسوب کر دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ عذاب کا فرشتہ ہے.آج کل بھی لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشگوئیوں کے ماتحت
Page 312
جب عذاب آتے دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں جو دنیا کو ہلاک کرنے کے لئے آئے ہیں یہی الزام جبرائیل پر لگایاگیا تھاجسے اللہ تعالیٰ نے اِس آیت میں دُور کیا ہے.فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ اس وجہ سے اُس سے عداوت کرتے ہیں کہ اُس نے قرآن مجید کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے.اِس جگہ فَاِنَّہٗ لِاَنَّـہٗ کے معنوں میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے جبریل ؑ سے عداوت کرتے ہیں کہ اُس نے یہ کتاب کیوں نازل کی.حالانکہ یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے اندر کئی قسم کی خوبیاں رکھتی ہے اور جن کو دیکھتے ہوئے اس سے دشمنی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا.اِس جگہ یہود کے مذکورہ بالا شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے چار جواب دیئے ہیں.پہلاجواب تو یہ دیا ہے کہ کوئی فرشتہ اپنی طرف سے کلام نازل نہیں کر سکتا بلکہ اس کا نزول اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے.پس خواہ کوئی فرشتہ کلام نازل کرنے والا ہو.جبریل ہو یا میکا ئیل جسے وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں بہر حال کلام نازل کرنے والا تو خدا ہے اور اس کے کلام پر فرشتہ کی دشمنی کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے.کیونکہ کلام لانیوالے کے فرق سے کلام میں فرق نہیں آسکتا.پس اگر کسی قومی روایت کی وجہ سے جبرائیل سے نفرت بھی ہو تو اس کلام سے نفرت کس طرح جائز ہو سکتی ہے جو وہ لاتا ہے.وہ کلام تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گا اور اُس کا قبول کرنا ضروری ہو گا.باقی رہا یہ کہ جبریل اِسے کیوں لایا میکائیل کیوں نہیں لایا.سو جبرائیل نے اِسے خود نازل نہیں کیا.بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے.اور جب خدا کے حکم سے اُس نے اسے اُتارا ہے تو اِس سے دشمنی کیسی؟ اُس نے تو خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے.اِسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی برتری اور اس کی فضیلت کی ایک یہ بھی دلیل دی ہے کہ یہ تعلیم اِس نبی کے دل پر اتاری گئی ہے جس کی وجہ سے اس تعلیم نے اس کے جذبات کو اس کے تابع کر دیا ہے.اِس جگہ فلاسفروں کے خیالات اور نبیوں کے کلام میں یہ فرق بتایا گیا ہے کہ نبی پر جو کلام اُترتاہے وہ اُس کے دل پر نازل کیا جاتا ہے.مگر فلاسفر کے خیالات کا نزول اُس کے دماغ پر ہوتا ہے.فلاسفر بھی اچھی باتیں کہتا ہے مگر اُس کے جذبات اُس کے افکار کے تابع نہیں ہوتے اور وہ جو کچھ کہتا ہے اُس کے مطابق اُس کا عمل نہیں ہوتا.لیکن نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے اُس کا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے.انگریزوں میں کئی بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں جن کی کتابیں اخلاقی باتوں سے بھری ہوئی ہیں.لیکن اُن کا عمل دیکھ کر انسان کو سخت مایوسی ہوتی ہے.اِس کی وجہ یہی ہے کہ اُن کے فلسفہ کا نزول دماغ پر ہوتا ہے اور کلامِ الٰہی کا قلب پر جس کی وجہ سے کلامِ الٰہی انسان کی زندگی کو
Page 314
اور کسی کلام کے ماننے یا ردّ کرنے میں اصل سوال یہی قابلِ غور ہوتا ہے کہ وہ درست ہے یا غلط.پس اگر یہ کلام صحیح ہے اور اس میں بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور اُن کی ترقی کی تعلیم دی گئی ہے تو تمہیں کسی اور امر کو مدنظر رکھ کر اُسے چھوڑنا نہیں چاہیے.چوتھی بات یہ بتائی کہ یہ تعلیم ایسی ہے جو اپنے ماننے والوں کے لئے بُشْرٰی ہے.یعنی اُن کو بڑے بڑے انعامات کا وعدہ دیتی ہے.گویا اگر کوئی شخص صرف اس لئے کسی صداقت کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا کہ وہ بنفسہٖ صداقت ہے بلکہ وہ انعامات کا بھی طالب ہو تو اُسے یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص اِس پر سچے دل سے عمل کرے گا اُسے بڑے بڑے انعامات بھی ملیں گے.پس اس کو چھوڑنا اپنانقصان کرنا ہے.اس فقرہ میں بھی یہود کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ جبریل عذاب کا فرشتہ ہے.مگر اس کلام میں تو بشارتیں ہی بشارتیں بھر ی پڑی ہیں.پھر وہ عذاب کا فرشتہ کیسے ہوا؟ غرض بتایا کہ یہ بحث ہی لغو ہے کہ کلامِ الٰہی جبرائیل لاتا ہے یا میکائیل.کلام تو خدانازل کرتا ہے.پس اگر کلام کی وجہ سے کسی سے دشمنی ہونی چاہیے تو خدا سے ہونی چاہیے.جبرائیل جو ایک درمیانی واسطہ ہے اُس سے دشمنی کِس طرح جائز ہو سکتی ہے.مگر تم خدا کو تو اپنا دوست قرار دیتے ہوا ور جبرائیل جو اس کا ایلچی ہے اُسے گالیاں دینے لگ جاتے ہو.پھر دوسری طرف تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جبرائیل اُس پر کلام کیوں لایا.اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کا کلام تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اُن کی پیشگوئیوں کو پورا کرتا ہے.اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کا آنا اِس بات کی علامت ہے کہ جبریل تمہارا دشمن ہے تو یہ عجیب دشمنی ہے کہ اُسی کے کلام سے تمہاری کتابیں سچی ثابت ہو رہی ہیں.پھر اس کا ھُدًی اور بُشْرَیٰ ہونا بھی بتاتا ہے کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جبریل آگ اور عذاب کا فرشتہ ہے کیونکہ اس کے ذریعہ جو کلام نازل ہوا ہے.وہ ہدایت سے پُر ہے اور ایمان لانے والوں کو اعلیٰ درجہ کے رُوحانی انعامات سے سرفراز کرتا ہے.پس جبرائیل یا میکائیل کی بحث میں پڑ کر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے.اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ٖوسلم کو قبول کر لینا چاہیے.میں نے اس آیت میں فَاِنَّہُ کے معنے لِاَ نَّہٗ کے کئے ہیں.کیونکہ میرے نزدیک یہاں فَاء لام کے معنی میں استعمال ہوا ہے.مگر فَاء کے عام معنے قائم رکھ کر دوسرے معنے بھی کئے جا سکتے ہیں.مگر اس صورت میں یہ جواب محذوف ماننا پڑے گا.کہ فَـلَا وَجْہَ لِعَدَاوَتِہٖ.اِس سے عداوت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں.کیونکہ اُس نے اس
Page 315
کلام کو تیرے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے.اس میں بتایا کہ وہ لوگ جو جبریل سے دشمنی کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے اِس رسول کے دل پر اُتارا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اِذن سے اتارا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق اتارا ہے.پس اس سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی.اگر تم دشمنی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے کرو گے نہ کہ جبریل سے(۲)وہ تعلیم تمہاری کتابوں کی پیشگوئیوں کی تصدیق کرنے والی ہے.اگر جبرائیل کو تم سے دشمنی ہوتی تو وہ ایسی تعلیم جو تمہاری تعلیم کو پورا کرتی ہے نہ اتارتا.پس جبرائیل سے دشمنی کرنے کے یہ معنے ہیں کہ تم اپنی کتابوں سے بھی دشمنی کر رہے ہو.(۳) پھر یہ کلام اس حال میں اُترا ہے کہ وہ ہادی اور مُبشر ہے.جو شخص ہادی سے دشمنی کرتا ہے وہ گویا اپنی جان سے دشمنی کرتا ہے.اور جو شخص مبشر سے دشمنی کرتا ہے وہ اپنی آئندہ نسلوں سے دشمنی کرتا ہے.ہدایت انسان کے اپنے نفس سے تعلق رکھتی ہے اور بشارت آئندہ نسلوں کے ساتھ.ہدایت ورثہ میں نہیں دی جاتی.مگر دنیوی انعامات عام طور پر ورثہ میں چلے جاتے ہیں.پس فرمایا کہ یہودی لوگ منبع سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور درمیانی حالت سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور انتہائی حالت سے بھی دشمنی کرتے ہیں.(۱) منبع تو اللہ تعالیٰ ہے جس سے وہ دشمنی کرتے ہیں(۲) پھر وہ انبیاء جو دنیا میں اس کے ظل اور مظہر ہوتے ہیں اور ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں اُن سے دشمنی کرتے ہیں.(۳) پھر اپنی ذات کے بھی دشمن ہیں اور آئندہ نسلوں سے بھی دشمنی کرتے ہیں اور انہیں اُن انعامات اور افضال سے جو ایمان لانے سے اُن کو مل سکتے ہیں محروم کرتے ہیں.پس جبریل کی دشمنی کوئی معمولی دشمنی نہیں.جو اُس سے دشمنی کرتا ہے وہ دراصل اس سے نہیں بلکہ اللہ اور اپنی جان اور اپنی آئندہ نسلوں سے دشمنی کرتا ہے.دوسرے معنٰی کی صورت میں مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے آخر میں رکھا ہے.یعنی فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے.مگر چونکہ فقرہ لمبا ہو گیا تھا اس لئے اس کے بعد پھر اس کے ذکر کو دُہرادیا ہے.اور ساتھ ہی میکائیل کا بھی ذکر کر دیا ہے.کیونکہ جبرائیل کی دشمنی میکائیل کی بھی دشمنی ہے اور اس کے بعد اس کی اصل جزا بتا دی ہے.اوپر جو مضمون بیان ہوا ہے اس سے یہود کو یہ بتایا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر وحی الہٰی کا نزول خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور اسی نے ان کو نبی بنایا ہے.پس تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنا خدا تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے.اِسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کا انکار دراصل موسیٰ ؑ کا انکار ہے جس نے اس کی پیشگوئی کی تھی.اب تم خود سوچ لوکہ تم اس مخالفت میں کہاں تک حق بجانب ہو.
Page 316
مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَ مَلٰٓىِٕكَتِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ جِبْرِيْلَ وَ (تو اسے یاد رہے کہ) جو شخص (بھی ) اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور مِيْكٰىلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ۰۰۹۹ میکائیل کا دشمن ہوتو (ایسے) کافروں کا اللہ بھی یقیناً دشمن ہے.تفسیر.اِس میں بتایا کہ فرشتے تو ایک واسطہ ہیں جس طرح ہو ا آواز پہنچانے کا واسطہ ہے.پس جو شخص اُن سے عداوت رکھتا ہے وہ درحقیقت اُس سے عداوت رکھتا ہے جس نے ان کو بھیجا.اور اُس پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے انتخاب میں غلطی کی.پس اس قسم کے خیالات کے یہ معنے ہیں کہ یہود خدا سے دشمنی کرتے ہیں.کیونکہ ایلچی کی ہتک درحقیقت بادشاہ کی ہتک ہوتی ہے.پس جو شخص فرشتوں میں سے کسی کو بُرا کہتا ہے وہ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ اُس نے وحی الہٰی نازل کرنے کے لئے ایک ناقص ہستی کو تجویز کیا.پس جبریل کی دشمنی صرف ایک فرشتہ کی دشمنی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی دشمنی ہے.پھر جو جبریل کا دشمن ہے وہ تمام ملائکہ کا بھی دشمن ہے.کیونکہ جبریل خود ملائکہ میں سے ایک مَلک ہے.پھر جبریل کی دشمنی کے نتیجہ میں انسان تمام رسولوں کا بھی دشمن بن جاتاہے کیونکہ جبریل ابتدا سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر کلامِ الہٰی لاتا رہا ہے.آخر پھر جبریل کا ذکر کر کے یہود کو متنبہ کیا ہے کہ اس کو اپنا دشمن مت سمجھو ورنہ اس کی دشمنی تمہیں خدا تعالیٰ کے دشمنوں میں شامل کر دے گی.اور خدا تعالیٰ کے افعال پر جرح کرنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سب ملائکہ اور رسولوں پر بھی معترض ہو کیونکہ ان سب کی عزت ذاتِ باری تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ وابستہ ہے.پس رُوحانی سلسلہ کے کسی ایک رُکن پر الزام لگانا یااُس سے عداوت کا اظہار کرنا انسان کو ہدایت سے بہت دُور لے جاتا ہے اور ایسے اشخاص آخر اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں.یعنی اُن فیوض اور برکات سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں جو اس کے دوستوں پر نازل ہوتی ہیں اور اُن عذابوں کے مورد بن جاتے ہیں جو اُس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں.جبریل کے بعد میکائیل کا خصوصیت سے اس لئے ذکر کیا کہ یہود کا خیال تھا کہ میکال ان کا خاص مہربان فرشتہ ہے.اور وہ اسے اسرائیل کا محافظ فرشتہ یا شہزادہ خیال کرتے تھے (انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا زیر لفظ Michael)
Page 317
میکال کے معنے ہیں خدا کی مانند.جس کی وجہ تسمیہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس فرشتہ کا کام زیادہ تر صفتِ ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی اُس کے سپرد دنیا کا رزق اور خبر گیری ہے اور جبریل کا روحانیات کے ساتھ تعلق ہے اور وہ کلامِ الہٰی لاتا ہے.گویا ہدایت لانے کا کام جبرائیل کے سپرد ہے.اور بُشْریٰ یعنی دنیوی ترقیات کے سامان مہیا کرنا میکائیل کا کام ہے اور بشرٰی ہمیشہ ہدایت کے تابع ہوتی ہے.جب انسان اس تعلیم پر جسے جبرائیل لاتا ہے عمل کر کے مہدی بن جاتا ہے تب اُسے بُشْریٰ یعنی دنیوی انعامات حاصل ہوتے ہیں.پس جو شخص مہدی نہ ہو وہ دنیوی انعامات بھی حاصل نہیں کر سکتا.اِسی طرح جو شخص جبرائیل سے دشمنی کرے گا میکائیل خود بخود اس کا ساتھ چھوڑ دے گا اور دشمن ہو جائیگا.غرض یہود کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم جبریل سے دشمنی کرو گے تو میکال بھی تمہارا دشمن ہو جائے گا اور اس طرح تمہارا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے.جبریل اور میکال کے دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد تاکید بھی ہے.یعنی جو کوئی ان کا دشمن ہو گا اُسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی دشمنی میں اللہ اور اس کے ملائکہ اور اُس کے تمام رسولوں کی دشمنیاں بھی شامل ہیں.پھر ان فرشتوں کا دوبارہ ذکر اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ فرشتے اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں وہ صرف ایک درمیانی واسطہ ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃو السلام نے فرشتہ کی مثال ہوا سے دی ہے (توضیح مرام روحانی خزائن جلد ۳ صفحہ ۹۴)یعنی جس طرح کلام کرنے والے اور سُننے والے کے درمیان ہوا کا واسطہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان فرشتہ واسطہ ہوتا ہے.اگر کوئی شخص اس واسطہ سے دشمنی کرتا ہے جو ایک ضروری چیز ہے تو دراصل اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز سے نہیں بلکہ اُس سے دشمنی کرتا ہے جس نے اس واسطہ کو بنایا ہے.کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب میں غلطی کی ہے.پس دراصل جبرائیل کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے اور جو آقا کا دشمن ہوتا ہے ماتحت بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں.اس لئے فرمایا کہ میکائیل بھی ان کا دشمن ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ آقا ہے اور باقی سب اس کے تابع ہیں.جو زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں.اگر زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ جائے تو ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ جاتی ہے.اسی طرح جبریل کی دشمنی سے نہ صرف وہی بلکہ تمام ملائکہ دشمن ہو جاتے ہیں اور ایک کڑی کے ٹوٹنے سے ساری زنجیر بے کار ہو جاتی ہے.یہود میکائیل کو اسرائیل کا شہزادہ اور اپنا دوست اور محافظ سمجھتے تھے.اس لئے اُس کا خاص طو ر پر ذکر کرکے بتایا کہ جبرائیل ؑ کی دشمنی سے وہ بھی تمہارا دشمن بن گیا ہے.پھر میکال کا اس لئے بھی خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب اُن کی کسی مقدس
Page 318
ہستی کو کوئی نادان بُرا کہے تو وہ ضِد اور تعصب کی وجہ سے دوسرے کی مقدس ہستیوں کو بھی بُرا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں.چونکہ ممکن تھا کہ کسی وقت مسلمانوں میں سے بھی بعض نادان یہود کی ضِد کی وجہ سے میکال کو بُرا بھلا کہنا شروع کر دیتے اور ان دونوں فرشتوں کو یہود اور مسلمانوں کے خاص محافظ فرشتے قرار دے کر ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑاکر دیا جاتا.اِس لئے اس غلطی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے خدا تعالیٰ نے میکال کا نام علیٰحدہ بھی لے دیا تاکہ یہود جب مسلمانوں کے سامنے یہ کہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے تو مسلمان ان کے مقابلہ میں ان کی اس عداوت کی وجہ سے یہ نہ کہہ دیں کہ اچھا اگر جبرائیل تمہارا دشمن ہے تو میکال ہمارا دشمن ہے.اِس خطرہ کو دُور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے میکال کا ذکر خصوصیت سے فرما دیا اور بتایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مقدس ہستیاں ہیں.ان سے عداوت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی.اگر یہود جبریل کے دشمن ہیں تو تم میکال کو بُرا نہ کہو.بائیبل سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کو رزق دینے والا اور لوگوں کی خبر گیری کرنے والا فرشتہ میکال ہے.چنانچہ دانیال باب ۱۰ آیت۱۳ میں لکھا ہے کہ ’’میکاایل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا.اور میں شاہانِ فارس کے پاس رُکا رہا.‘‘ اور آیت۲۱میں لکھا ہے.’’جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں اور تمہارے مؤکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مدد گار نہیں ہے.‘‘ اِس طرح دانی ایل باب۱۲ آیت ۱ میں لکھا ہے:.’’اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لئے کھڑا ہے اُٹھے گااور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہو گا کہ ابتدائے اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہو گا.اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہو گا رہائی پائے گا.‘‘ غرض میکال کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اس کے ساتھ دشمنی کرنے سے روکا ہے اور بتایا ہے کہ ایسا نہ ہو تم ضد میں آکر اپنا نقصان کر لو اور یہود کے مقابلہ میں میکال سے دشمنی کرنے لگو.فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَمیں ضمیر کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ ضمیر کے استعمال سے یہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کا مرجع میکال کو نہ قرار دے دیں.پس ضمیر کی بجائے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بتایا کہ اگر تم جبریل کو بُرا
Page 319
بھلا کہو گے اور اپنی اس عادت کو ترک نہیں کرو گے تو پھر خدا بھی تمہارا دشمن ہو جائے گا.اور تمہاری ناکامی و نامرادی میں کوئی شبہ نہیں رہے گا.وَ لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ١ۚ وَ مَا يَكْفُرُ بِهَاۤ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ۰۰۱۰۰ اور ہم نے یقیناً تجھ پر کھلے کھلے نشانات نازل کئے ہیں اور نافرمانوں کے سوا ان کا انکار کوئی نہیں کرتا.تفسیر.عیسائی لوگ اس سورۃ کی آیت وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ (البقرۃ:۱۱۹) سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیوں ہم سے براہ راست اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا؟ یا کیوں ہمارے پاس تُو کوئی نشان نہیں لاتا.اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بیّنٰت کا لفظ آجائے جیسا کہ پچھلے رکوع میں ہی آچکا ہے تو وہ اِس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ مسیحؑ نبی نہیں تھا بلکہ نبیوں سے بالا ہستی تھی.مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے لئے وہی الفاظ آجائیں تو نہایت خاموشی سے گزر جاتے ہیں.بلکہ کفار کے مطالبہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آیات نہیں دکھائی جاتیں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے کوئی نشان نہیں دکھایا.حالانکہ اگر کفار کے آیات مانگنے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تو پھر یہی اعتراض حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی پڑ سکتا ہے.اور اُن کے متعلق بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا.چنانچہ متی باب ۱۲ آیت ۳۸،۳۹ میں لکھا ہے کہ ’’تب بعضے فقیہیوں اور فریسیوں نے جواب میں کہا.کہ اے اُستاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں.اُس نے انہیں جواب دیا اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرامکار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان اُنہیں دکھایا نہ جائے گا.‘‘ اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اُس وقت تک جب آپ نے یہود کو یہ جواب دیا تھا کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا.اور پھر اس جواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری عمر یہود کو کوئی نشان نہیں دکھایا کیونکہ یونس نبی سے مماثلت کا نشان وہ ہے جو اُن کی موت کے وقت ظاہر ہوا.اور یہود کا سوال یہ تھا کہ ہمیں اب
Page 320
کوئی نشان دکھایا جائے.مگر جب اُن سے کوئی نشان طلب کیا گیا تو انہوں نے بقول انجیل یہ کہا کہ اس زمانہ کے بد اور حرامکار لوگوں کو کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا.گویا انہوں نے دشمن کے مقابلہ میں اپنے عجز کا اقرار کر لیا.اور کہا کہ اُن کو سوائے یونس نبی کے معجزہ کے اور کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا اور آئندہ کے لئے بھی صرف ایک نشان کا انہوں نے وعدہ کیا مگر یہ وعدہ بھی غلط ہو گیا.کیونکہ عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام صلیب پر مر گئے تھے.اور مر کر ہی وہ قبر میں گئے تھے.حالانکہ یونس علیہ السلام سمندر میں گرے تو زندہ رہے.پھر مچھلی نے اُن کو نگلا تب بھی وہ زندہ ہی رہے.اور پھر اس کے پیٹ میں سے بھی زندہ ہی نکلے.مگر مسیح علیہ السلام تو اُن کے نزدیک صلیب پر ہی مر گئے تھے.گویا ایک ہی معجزہ جس کے دکھانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا.اُس کے متعلق مسیحیوں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں دکھایا گیا.اور اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی نشان نہیں دکھایا.مگر اس کے مقابلہ میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖوسلم کو بڑی کثرت کے ساتھ معجزات دیئے گئے تھے.عیسائی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف جو معجزات منسوب کئے جاتے ہیں انہیں ہم معجزہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے مگر یہ کہنا کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے معجزات کامنکر ہے حدّ درجہ کا ظلم ہے.قرآن کریم نہایت واضح الفاظ میں اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو بڑے بڑے معجزات دیئے گئے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَ لَقَدْ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ یعنی ہم نے یقیناً تجھ پر کھلے کھلے نشانات نازل کئے ہیں.اس جگہ آیات بیّنات سے وہ تمام نشانات مراد ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے اور جن کی نظیر نہ موسیٰ ؑ کے نشانوں میں مل سکتی ہے اور نہ عیسیٰ ؑ کے نشانوں میں.مگر فرمایا.وَ مَا يَكْفُرُ بِهَاۤ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ باوجود اِس کے کہ نشاناتِ الہٰیہ کی بارش برس رہی ہے پھر بھی اطاعت سے نکل جانے والے لوگ انکار پر کمر بستہ ہیں.مگر اُن کا انکار اُنہیں کیا فائدہ دے سکتا ہے.جس طرح پہلے نبیوں کے منکر تباہ ہوئے اُسی طرح یہ بھی تباہ ہوں گے.اور اللہ تعالیٰ اس سکیم کو پورا کر کے رہے گاجس کے لئے وہ متواتر اپنے نبیوں سے ہر زمانہ میں پیشگوئیاں کرواتا چلا آیا ہے.
Page 323
ان معنوں میں مُصّدِق ہیں کہ آپ نے اپنی بعثت سے اُن کی پیشگوئیوں کو سچا ثابت کر دیا اور موسیٰ ؑ اور عیسیٰ ؑ اور دوسرے اسرائیلی نبیوں کی سچائی ظاہر ہو گئی.اب یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنی کتاب کی لاج رکھتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں یا اسے ردّ کر دیں.مگر جیسا کہ آیت کے اگلے ٹکڑہ میں بیان کیا گیا ہے یہود نے اِن پیشگوئیوں سے کوئی فائدہ نہ اُٹھایا اور انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا.اس جگہ کِتٰب اللّٰہِ سے مراد تورات ہے اور اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دینے سے یہ مراد ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسی تذلیل کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ گویا وہ اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک رہے ہیں.حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انہیں ادب کرنا چاہیے تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو الگ رہی نبیوں کے کلام کی تحقیر بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے کسریٰ کو جو تبلیغی خط لکھا تھا وہ اُس نے اپنی بیوقوفی سے پھاڑ ڈالا تھا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا.اس نے ہمارا خط پھاڑا ہے خدا اس کی سلطنت کو تباہ کرے(بخاری کتاب العلم باب ما یذکر فی المناولۃ....).چنانچہ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی.اگر محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خط کو پھاڑ کر انسان اتنی سزا کا مستحق ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکنے والا اور اُس کی تذلیل کرنے والا کتنی سزا کا مستحق ہو گا.جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خط پھاڑنے والے کو تباہ کر دیتا ہے تو وہ اپنے خط کی تذلیل کس طرح برداشت کر سکتا ہے.وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ١ۚ وَ مَا نیز وہ (یعنی یہودی )اس (طریق عمل) کے پیچھے پڑ گئے جس کے پیچھے سلیمان ؑ کی حکومت کے زمانہ میں( اس کی كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَ لٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ حکومت کے) باغی پڑے رہتے تھے.اور سلیمان ؑ کافر نہ تھا بلکہ (اس کے ) باغی کافر تھے.وہ لوگوں کو دھوکا دینے السِّحْرَ١ۗ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ والی باتیں سکھاتے تھے اور (بزعم خود) اس بات کی (بھی نقل کرتے ہیں) جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت
Page 325
کے معنٰی میں اس کا استعمال قرآن کریم میں بھی آتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا (الشّمس:۳) ہم چاند کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جبکہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے.اور معنوی پیروی کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ (البقرۃ : ۱۲۲) یعنی وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اسی طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے.گویا وہ اتباع کا حق ادا کردیتے ہیں.عَلیٰ اور معنوں کے علاوہ فِیْ کے معنیٰ میں بھی مستعمل ہے(مغنی اللبیب ).جیسا کہ قرآن کریم کی آیت اِنْ کُنتُمْ عَلٰی سَفَرٍ میں عَلٰی بمعنیٰ فِیْ ہی استعمال ہو ا ہے.مُلْک کے(۱) ایک معنے اَلْعَظْمَۃُ وَالسُّلْطَانُ کے ہیں یعنی غلبہ اور دبدبہ(۲) اس کے دوسرے معنی ہیں اِحْتِوَاءُ الشَّیْ ءِ وَالْقُدْرَۃُ عَلَی الْاِسْتِعْلَا ءِ بِہٖ یعنی کسی چیز پر کسی شخص کا قبضہ کر لینا.اس پر حاوی ہو جانا اور اس کو اپنے منشا کے مطابق کر لینا (لسان العرب) یہ معنے بھی دبدبہ کا ہی مفہوم رکھتے ہیں(۳) اس کے تیسرے معنے مُلک کے بھی ہیں جو عام مروّج ہیں.سِحْر اس کے عربی میں کئی معنے ہیں.اوّل.کُلُّ مَالَطُفَ مَأْخَذُہٗ وَدَقَّ.ہر وہ بات جس کا ماخذ نہایت باریک اور دقیق ہو.اور جس کی اصلیت معلوم نہ ہو سکے سحر کہلاتی ہے.دوم.فساد.سوم.اِخْرَاجُ الْبَاطِلِ فِیْ صُوْرَۃِ الْحَقِّ.باطل کو سچائی کی صورت میں پیش کرنا.چہارم.خِدَاعٌ یعنی دھوکا.پنجم.ملمع سازی.ششم.راستہ سے ہٹادینا.چانچہ سَحَرَہٗ کے معنے ہوتے ہیں صَرَفَہٗ اُسے ایک طرف کر دیا.(اقرب الموارد) مَلَکَیْنِ.مَلَکٌ کے اصل معنے فرشتہ کے ہیں.لیکن مجازاً مَلَک کا لفظ نیک انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے.اور چونکہ اس کی ایک قراء ت مَلِکَیْنِ بھی آتی ہے(بحرِ محیطزیر آیت ھٰذا) اور قراء ت صحیح معنوں کی مفسر ہوتی ہے اس لئے یہ دوسری قرا ء ت اس کے صحیح معنوں کو حل کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ اس جگہ دو فرشتے مراد نہیں بلکہ دو فرشتہ خصلت بزرگ مراد ہیں جن کو ان کی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے مَلَک قرار دیا گیا ہے.قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہمَلَک کا لفظ استعارۃً اچھے اور نیک انسان پر بھی بولا جاتا ہے.جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت آتا ہے کہ اِنْ ھٰذَ ا اِلَّا مَلَکٌ کَرِیْمٌ (یوسف :۳۲) یعنی یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے.اور مراد یہ ہے کہ بڑا بزرگ اور خوبیوں والا انسان ہے.مَلَک کے اس استعمال کو مدّنظر رکھ کر مَلَکَیْن کے معنے یہ ہوئے کہ دو نہایت اچھے شریف اور فرشتہ خصلت بزرگ.اور یہی معنیٰ اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں.مَلَک سے مراد فرشتہ کی بجائے انسان ہم اس لئے بھی سمجھتے ہیں کہ اس جگہ ان دونوں کا کام یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے تھے اور انہیں اہم باتیں سکھاتے تھے.
Page 326
اور قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ ملائکہ انسانوں کی طرف اس طرح نہیں بھیجے جاتے کہ وہ انسانوں میں مِل جُل کر رہیں اور انہیں پڑھائیں اور سکھائیں.بلکہ ہمیشہ انسان رسول ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کئے جاتے رہے ہیں.چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے.وَ مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰۤى اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا (بنی اسرائیل:۹۵) یعنی لوگوںکو ہدایت کے قبول کرنے سے سوائے اس بات کے اور کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی نبی آنا تھا تو کیا آدمیوں میں سے ہی آتا؟ فرماتا ہے تو انہیں جواب میں کہدے کہ لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنَ۠ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا (بنی اسرائیل:۹۶) اگرزمین میں آدمیوں کی بجائے فرشتے ہوتے جو اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم بے شک کسی فرشتہ ہی کو رسول بنا کر بھیج دیتے.مگر چونکہ دنیا میں آدمی بستے ہیں اس لئے ہم بھی آدمیوں ہی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں.غرض چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ہمیشہ آدمی ہی رسول بن کر آتے ہیں اس لئے اس جگہ بھی انسان ہی مراد ہو سکتے ہیں فرشتے نہیں.پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بطور واقعہ کے فرماتا ہے کہ جس قدر رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سب انسان ہی تھے.جیسا کہ فرماتا ہے.وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (الانبیاء : ۸)یعنی اے محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے وہ سب کے سب انسان تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے اور اگر تم کو اس بات کا علم نہیں تو تم ان قوموں سے جن کے پاس کلام الہٰی ہے پوچھو کہ دنیا میں انسان نبی ہو کر آتے تھے یا فرشتے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بتادیا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی آزمائش یا ہدایت کے لئے مَلک رسول نہیں آئے بلکہ ہمیشہ مرد رسول آتے رہے ہیں.اور فرشتے صرف انبیاء و اولیاء پر کلامِ الہٰی لے کر نازل ہوتے ہیںیا شاذ و نادر کے طو ر پر بعض دوسرے لوگوں کو بھی کشفی طور پر نظر آ جاتے ہیں اور چونکہ اس آیت میں بتایا ہے کہ وہ دونوں مَلک دنیا میں رہتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے اس لئے اس جگہ مَلَکین سے دو فرشتے نہیں بلکہ دو فرشتہ خصلت بزرگ مراد ہیں جو اپنی نیکی او ر تقویٰ کی وجہ سے یَفْعَلُوْنَ مَا یُوْمَرُوْنَ میں شامل تھے.یعنی انہیں جو بھی حکم دیا جاتا اُس پر وہ چلتے تھے.اور اُس کی کسی حالت میں بھی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے.اور چونکہ ملائکہ کی بھی یہی صفت ہے.اس لئے ان کا نام بھی مَلک رکھا گیا.پھر اس کی ایک قرأت جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے مَلِکَیْن بھی آئی ہے.اس سے بھی ان معنوں کی تصدیق ہو جاتی ہے.معلوم ہوتا ہے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ھَارُوْت و مَارُوْت دو فرشتے تھے جنہوں نے بابل میں آکر لوگوں کو سحر سکھلایا اور اُن کے ایمان کی آزمائش کی وہ قرآن کریم کے مطالب سے آگاہ نہیں.ورنہ جب دنیا میں
Page 327
فرشتے نہیں بستے تو فرشتے رسول بن کرکیوں آئیں پس یہ قطعی طور پر محال ہے کہ بجائے انسان کے فرشتے لوگوں کی ہدایت کے لئے آیا کریں.تاریخ پڑھ کر دیکھ لو ہمیشہ رَجُل ہی نبی بن کر آیا ہے.نہ کبھی عورت نبی بنی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی غیر انسان نبی ہو کر آیا ہے.پس یا تو اس کے یہ معنے کرنے پڑیںگے کہ ھَارُوْت ومَارُوْت دونوں ملکوتی صفات انسان تھے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اِنْ ھٰذَ ا اِلَّا مَلَکٌ کَرِیْمٌ.اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ اگر وہ واقعی فرشتے تھے تو وہ دو نبیوں پر اُترے تھے نہ کہ عام لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے کیونکہ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت لَوْكَانَ فِي الْاَرْضِ مَلٰٓىِٕكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَىِٕنِّيْنَ۠ (بنی اسرائیل :۹۶) سے ظاہر ہے فرشتے مُطْمَئِنِّیْن کی طرف آیاکرتے ہیں یعنی ان لوگوں کی طرف جو نیک اور پاک اور خدا رسیدہ ہوں.بدیوں سے کلّی طور پر اجتناب کرنے والے ہوں.ہر قسم کے رذائل سے محفوظ ہوں اور الہٰی انعامات اور برکات کے مورد ہوں.مُطْمَئِنِّیْن کی یہ وہ تعریف ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان کی ہے يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ.ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ.وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.(الفجر:۲۸تا۳۱)پس مُطْمَئِنِّیْن سے مراد وہ لوگ ہیں جو نفس مُطمئِنّہ رکھنے والے ہوں.یہ مراد نہیں کہ اطمینان سے زمین میں کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہوں اورلڑائیوں سے اجتناب کرتے ہوں.اور درحقیقت ایسے ہی لوگوں پر ملائکہ کلامِ الٰہی لے کر نازل ہوتے ہیں.یہ کبھی نہیں ہوا کہ کفار پر ملائکہ نازل ہوئے ہوں اور اُنہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائے گئے ہوں.ھَارُوْت.ھَرَتٌسے نکلا ہے اور ھَرَتٌ کے معنے ہیں پھاڑنا.(تاج ) پس ھَارُوْت کے معنے ہیں بہت پھاڑنے والا.(المنجد) مَارُوْت.مَرَتٌ سے نکلا ہے جس کے معنے توڑنے کے ہیں.پس مَارُوْت کے معنے ہیںبہت توڑنے والا.(تاج ) فِتْنَۃٌ.وہ آزمائش جس کے ذریعہ سے کسی انسان کی خوبی یا برائی معلوم کی جائے.اور بھلے بُرے کو پرکھا جائے اور خیر و شر کا پتہ لگایا جائے.جیسے امتحان کے ذریعہ انسان کی خوبی یا نقص کو ظاہر کر دیا جاتا ہے.(المنجد) تفسیر.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃوالسلام مئی ۱۹۰۸ء میں فوت ہوئے تھے.غالباً آپ کی وفات کے ایک ماہ بعد کی بات ہے کہ مجھے الہام ہوا.اِعْـمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُکْرًا.اے دائود کی نسل شکر گذاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال بجا لائو.اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سلیمان تو استعمال نہیں فرمایا مگر آلِ دائود کہہ کر
Page 329
بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہا ئے گی.اور خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم نہیںجانتے.مگر آخر اُن کی بات درست نکلی کہ آدمؑ کی نسل دنیا میں شیطان کے قبضہ میں چلی گئی.اُن فرشتوں نے خدا تعالیٰ کو کہاکہ اگر ہم دنیا میں ہوتے تو یہ شرارتیں کیوں ہوتیں.اِس پر اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو دنیا میں بھیج دیا.اور فرمایا کہ تم دنیا میں جائو ہم دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو.وہ دنیا میںآگئے اور لوگوں میں رہے.ان کو اسم اعظم اور جادو آتا تھا.وہ لوگوں کو جادو سکھاتے رہے اور خدا تعالیٰ پر یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ لوگ جان بُوجھ کر کفر اختیار کر تے ہیں وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ اِس کا سیکھنا منع ہے.اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے.اب جس کی مرضی ہے سیکھ لے اور جس کی مرضی ہے نہ سیکھے مگر لوگ پھر بھی سیکھ لیتے.وہ صرف مردوں کو سحر سکھایا کرتے تھے جس کے نتیجہ میں عورتوں سے جدائی ہو جاتی تھی.اِسی دوران میں زُہرہ نامی ایک کنچنی اُن سے اسم اعظم سیکھنے کے لئے آئی.وہ دونوں اُس پر عاشق ہو گئے.چنانچہ اُن دونوں نے اُسے ایک دن شراب پلائی اور اُس کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہوئے.اِس پر خدا تعالیٰ نے اُن سے پُوچھا کہ اب بتائو اِس کی سزا میںتم دنیا میں کنوئیں میں لٹکنا چاہتے ہو یا قیامت کے دن تم کو سزا ملے چونکہ انہوں نے خدا کا عذاب دیکھا ہوا تھا اس لئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہی ہمیں عذاب دےدیا جائے.چنانچہ بابل میں ایک اندھے کنوئیں میں گرائے گئے اور وہ اُس میں اب تک لٹکے ہوئے ہیں.اور زُہرہ جس نے اسم اعظم سیکھا تھا عوام کے نزدیک ستارہ بن کر آسمان پر چلی گئی.(تفسیر محاسن التـأویل للقاسمی زیر آیت ھٰذا) اُن کے نزدیک آسمان پر جو زہرہ ستارہ دکھائی دیتا ہے وہ وہی کنچنی ہے جو ہاروت و ماروت کے پاس آئی تھی.کشمیریوں نے تو اس کے متعلق حد ہی کر دی ہے.وہ کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کا کنواں کشمیر میں ہے.گویا وہ بابل سے اُٹھ کر وہاں جا پہنچے تھے.اِن خرافات کو پیش کر کے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا وہ درست نکلا.اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم ؑکو بھیجا.مگر اُس کی نسل خراب ہو گئی.پھر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے.مگر وہ بھی انسانوں کی وجہ سے خراب ہو گئے.حالانکہ اُن کا یہ نتیجہ سراسر غلط ہے.خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ ملائکہ سب کے سب نیک ہوتے ہیں اور اُن میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں پایا جاتا.لیکن انسانوں میں بعض نیک اور بعض بد ہوتے ہیں.اگر انسان خراب ہو گئے تھے تو اعتراض ہوتا ہے کہ آدمیوں کے مقابلہ میں فرشتے بھی خراب ثابت ہوئے.اس سے تو اعتراض دور نہ ہوا بلکہ اور بھی پختہ ہو گیاکہ خدا تعالیٰ نے جن کے متعلق فرمایا تھاکہ وہ نہیں بگڑیں گے.وہ بھی بگڑ گئے.انسانوں کے متعلق تو فرمایا تھا کہ اُن میںکچھ نیک اور کچھ بد ہمیشہ رہیں گے مگر فرشتوں کے متعلق تو یہ کہا گیا تھا کہ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ
Page 331
اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تین وقت کے اعمال کا ذکر ہے.وہ عمل جو تینوں دفعہ ہواکوئی خفیہ بات یا سازش ہے.یہ عمل مندرجہ ذیل تین مواقع پر ہوا ہے.اوّل.حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں دوم.بابل میں سوم.رسول کریم صلی اﷲ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت اس کا وقوع وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ کے الفاظ سے ثابت ہے.اور بابل کے موقع کے لئے مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْ تَ کے الفاظ شاہد ہیں.اور رسول کریم صلی اﷲعلیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ میں اس کا صدور وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْسے ثابت ہے.بلکہ دوسری آیت وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْاسے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے.غرض آیت کے یہ تین حصے اس عمل کے تین دفعہ صادر ہونے پر دلالت کرتے ہیں.چوتھی بات اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ تینوں دفعہ اس عمل کا صدور یہود سے ہوا تھا.یہ چار باتیں ہمارے معنوں کو محدود کر دیتی ہیں.پس وہی معنے صحیح ہوں گے جو مذکورہ بالا چار باتیں اپنے اندر رکھتے ہوں یعنی وہی معنیٰ ان آیات کے مطابق ہو سکتے ہیں جو (۱) ایسے عمل پر دلالت کرتے ہوںجو تین دفعہ صادر ہوا ہو.(۲) جو کسی ایسے عمل پر دلالت کرتے ہوںجو خفیہ سازش یا خفیہ سوسائٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں.(۳) جو ثابت کرتے ہوں کہ اُن کا ایک وقوع حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت.دوسرا بابل میں اور تیسرا رسول کریم صلی اﷲعلیہ وآلہٖ وسلم کے وقت ہوا.(۴) جو معنی یہ بتائیں کہ تینوں واقعات یہود کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں.پس جو معنے اس کے خلاف ہوں گے آیت ان کو ردّ کردے گی.اسی طرح جو معنے مفسّرین نے بیان کئے ہیں لازماََ اُن میں بھی ان چاروں پہلو ؤں میں سے کوئی پہلو ضرور مفقود ہو گا یعنی (۱) یا تو یہود کا ان سے تعلق نہ ہوگا.(۲) یا وہ تین دفعہ نہ ہوا ہو گا.(۳) یا ان تینوں موقعوں پر نہ ہوا ہو گا.
Page 332
(۴) یا اس میں خفیہ سازش ا ورسوسائٹیوں کا ذکر نہ ہو گا.اب ہم دیکھتے ہیںکہ وہ کونسی بات ہے جو اِن چاروں اصول پر حاوی ہو.اور پھرتین زمانوں پر حاوی ہو اور انہیں زمانوں پر حاوی ہو جن کا اس جگہ ذکر ہے.ان چاروں اصولوں میں سے ایک اصل ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے جس پر ہم اپنی تحقیق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور وہ یہ کہ وہ معنے ایسی خفیہ سازش اور سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں.جو مرد اور عورت کے درمیان تفریق پیدا کر دیتی تھی.یعنی وہاں یہ شرط پائی جاتی تھی کہ اس میں صرف مر د ہی داخل ہو سکتے ہیں عورتیں نہیں.اس شرط سے ہمارے لئے تحقیقات میں بہت سی سہولت پیدا ہو جاتی ہے.اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی سوسائٹی ہے جو مرد اور عورت میں جدائی ڈالتی ہو اور آیا اس کا تعلق ان زمانوں کے ساتھ ہے ؟ سو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی سوسائٹی ہے.جس میں مر د اور عورت میں تفریق پیدا کی جاتی ہے.اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہٖ و سلم کے زمانہ تک نظر آتی ہے.بلکہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے تک بھی چلی آئی ہے.اور وہ فریؔ میسنز کی سوسائٹی ہے.جو پنجاب میں جادو کی سوسائٹی کہلاتی ہے.یہ ایک خفیہ سوسائٹی ہے.جس کا اصول یہ ہے کہ عورتیں اس کی ممبر نہیں ہو سکتیں صرف مرد ہی ممبر ہوسکتے ہیں.اس سے ہم اصل مضمون کے قریب ہو جاتے ہیں اور ہم اس پر اپنی تحقیق کی بنیاد رکھ سکتے ہیں.کیونکہ یہ سوسائٹی مخفی بھی ہے اور پھر مردوں ہی کو اپنے اندر داخل کرتی ہے.یہ امر یا د رکھنا چاہیے کہ موجودہ فری میسن سوسائٹی کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں اِس میں صرف اُس فری میسن سوسائٹی کا ذکر ہے جس کا تعلق تین زمانوں سے ثابت ہو اور تاریخی واقعات سے بھی اُس کی تصدیق ہو.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ کسی فری میسن سوسائٹی کا آج تک تسلسل قائم نہیں رہا.کوئی چار سو سال تک رہی کوئی پانچ سو سال تک.کوئی بارھویں صدی میں مٹ گئی کوئی پندرھویں صدی میں.کوئی اٹھارویں صدی میں قائم ہوئی اور پھر اسی صدی میںمٹ گئی اور کوئی انیسویں صدی میں قائم ہوئی.پس ہم کسی ایک سوسائٹی کے اصول پر قطعی بنیاد نہیں رکھ سکتے.کیونکہ بہت سی سوسائٹیاں قائم ہوئیں اور انھوں نے پہلوں کی بعض باتیں لے لیں اور بعض ترک کر دیں.مگر ایک اصل مَیں نے یہ بھی بتایا ہےکہ ایسی خفیہ سوسائٹی کا یہود سے تعلق ہونا چاہیے.کیونکہ ان تینوں باتوں کا یہود سے ہی تعلق ہے.اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا فری میسن سوسائٹی کایہود سے کوئی تعلق ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ جیوش انسا ئیکلوپیڈیا جلد۵ جس میں یہودیوںکے متعلق فری میسنری Freemasenary کے ماتحت اس بات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فری میسنوں کا یہود سے کوئی تعلق ہے.اسی سے اس بات
Page 333
کاواضح طو رپر ثبوت ملتا ہے کہ یہود کا فری میسنوں سے تعلق رہا ہے.اوّل تو انسان اسی مضمون سے سمجھ سکتا ہے کہ اُن کا اس سوسائٹی سے تعلق رہا ہے ورنہ انہیں جواب دینے کی کیا ضرورت تھی.لیکن اس کے علاوہ خود اس مضمون سے بھی واضح ہے کہ یہود کا اس سوسائٹی سے تعلق رہا ہے.چنانچہ جیوش انسا ئیکلوپیڈیامیں لکھا ہے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیںکہ فری میسن سوسائٹیوں کے اصولوں میں یہودی نشانات پائے جاتے ہیںاور یہ بات سوسائٹی کا ان سے تعلق ظاہر کرتی ہے.کیونکہ ان نشانات کا ابتدائی تعلق ان انجینئروں کے ساتھ ثابت ہے جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ معبد میں دخل تھا.اس سے ظاہر ہے کہ اس سوسائٹی کی علامات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پہلے تیار کردہ معبد کے انجینئروں کی طرف منسوب کی جاتی ہیں.چنانچہ یہ سوسائٹی بھی تسلیم کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا پہلا معبد بنایااس وقت سے ہماری سوسائٹی کی ابتدا ہوئی.بلکہ بعض لوگ اس سے بھی اوپر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے ہماری ابتدا ہوئی ہے.وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ؑ ہمارے گرینڈ ماسٹر ہیں.جیوش انسا ئیکلوپیڈیامیں لکھا ہے کہ ان کی روایات میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اُن کا حورام ابیّ سے تعلق ہے جس نے مسجد بنائی تھی اورجس کا ذکر۲.تواریخ باب۲آیت۱۳و۱۴میں اس طرح آتا ہے.’’اور اب میں حورام ابیّ ایک ہوشیار شخص کوجو کہ امتیاز کرنا جانتاہے بھیجتا ہوں وہ دان کی بیٹیوںمیں سے ایک عورت کا بیٹا ہے.پر اس کا باپ صُور کا ایک شخص ہے.وہ سونے اور روپے ا ورپیتل اور لوہے اور پتھراور لکڑی اور ارغوانی اور آسمانی اور کتانی اور قرمزی اور ہر طرح کی نقاشی کا کام جانتا ہے.اور ہر ایک منصوبے کو جو اس سے پوچھا جاوے اس کی ایجاد کرنے میں ماہر ہے.وہ تیرے ہنرمندوں اور میرے مخدوم تیرے باپ داؤد کے ہنر مندوں کے ساتھ سب کا م بناوے گا.‘‘ فری میسنوںکی روایات کے مطابق مسجد بننے کے بعدتین مزدوروں نے حورام ابیّ کو قتل کر دیاتھا.اور فری میسنوں کی رسموں میں اس کی موت کو بڑا بھاری بھید قراردیاجاتا ہے.مصنف کہتا ہے کہ ہم اس کا حل یوں کر سکتے ہیں کہ ابیّ لٹریچر میں جو روایات آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انجینئروں نے کام پورا کر لیا تو ان کو اس وجہ سے قتل کروا دیا گیاکہ وہ مسجد کو ُبت خانہ نہ بنا دیں اور اس طرح اس کی ہتک نہ ہو.ان کی روایات میں یہ آتا ہے کہ حورا م حنوک کے پاس آسمان پر بیٹھا ہے.فری میسنوں کی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ باقی انجینئروں کو بھی قتل کر وادیا گیا تھا مگر حورام آسمان پر اُٹھا لیا گیا.مصنف کہتا ہے کہ ہماری
Page 335
پر ہلاک کرنا چاہا اور اسے اُبلتے ہوئے تیل کے تالاب میں گرا دیا.لیکن اس کے دادا قابیل کی روح نے اس کو وہاں سے نکال کر بچا لیامگر ساتھ ہی اسے یہ بھی خبر دے دی کہ آخر دشمن غالب آ جائے گا.اسی کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاسدوں کو کچھ دے دلا کر تین انجینئروں کو قتل کروا دیا جن میں یہ بھی شامل تھا.اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کچھ خفیہ علامات مقرر کی ہوئی تھیں.جو اس نے خود وضع کی ہوئی تھیں.اور جواس کے اور اس کے ساتھیوں کے درمیان بطور راز کے تھیں جن کے ذریعہ وہ فوراً اکٹھے ہو جاتے تھے.(سِیکرٹ سوسائٹیز آف دی ورلڈ جلد۲ صفحہ ۱ تا۱۰ ) اس کتاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایکسپٹڈ میسنز (Accepted Masons ) کے طریق سے پہلے تمام فری میسنز سوسائٹیوں میں وہی علامات جا ری تھیں جو حورام کے وقت جاری تھیں.ان میں جو نئے لوگ داخل ہوتے اور ممبر بنتے تھے ان کو کچھ خفیہ باتیں عمل کرنے کے لئے بتائی جاتی تھیںاور حورام کا واقعہ بھی ان کو سنایا جاتا تھا.(جلد دوم صفحہ۱۰)یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جب کسی کو فری میسن بناتے تھے تو اسے حورام کا قصہ کچھ زبانی سنایا جاتا تھا اور کچھ ڈرامے کے طور پر دکھایا جاتا تھا.انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں یہ ذکر ہے.کہ حورام کا ذکر فری میسن کی علامات میںدُوہرایا جاتا تھا.چنانچہ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہ یہ پتہ لگ جائے کہ وہ علامات کیا ہیں.مگر وہ علامتیں اُس کے گلے میں بندھی ہوئی تھیں.جب اسے حضرت سلیمان ؑ نے قتل کیا تو انہیں اتار کر پھینک دیا.اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خفیہ انجمنیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت موجود تھیں اور وہ آپ کی دشمن تھیں اور آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کیاکرتی تھیںاور کہا جاتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُن کے لیڈر کو مروا دیا تھا.اُس کے بعض متبع اُسے اِتنا مقدس انسان سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ مرا نہیں بلکہ آسمان پر اُٹھا لیا گیا ہے.پس یہ لوگ یہودی تھے.اِن میں یہود کی علامات اور رسوم کا پایا جانا اور اُن کو حورام کی طرف منسوب کرنا اور حورام کااُن کے نزدیک آسمان پر اُٹھا یا جانا بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت یقیناً ایک خفیہ سوسائٹی تھی جس کا مقصد حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقصان پہچانا تھا.اِس کے بعد ہم بائیبل کو دیکھتے ہیں تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کچھ سوسائٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف تھیں گو اُن میں حورام کا نام نہیں آتا مگر بائیبل سے یہ پتہ ضرور لگتا ہے کہ یہود کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے دشمنی تھی.وہ انہیں کافر کہتے تھے اور اُن کی طرف وہی بات منسوب کرتے تھے جس کا قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر آتا ہے.
Page 336
حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف خفیہ سازشوں اور منصوبوں اور دھوکا دینے والے اشارات میں مخالفانہ کارروائیاں کرنے والے لوگوں کا جو ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے اس کے متعلق ۱.سلاطین باب ۱۱ آیت ۳،۴ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بُت پرستی کا الزام لگایا جاتا تھااور کہا جاتاتھا کہ آپ مشرک ہو گئے ہیں اور توحید کو ترک کر دیا ہے.چنانچہ لکھا ہے : ’’ اُس کی سات سو جو روئیں بیگمات تھیں اور تین سو حرمیں.اور اُس کی جورؤں نے اُس کے دل کو پھیرا.کیونکہ ایسا ہوا کہ جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اُس کی جورؤں نے اُس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کیا اور اُس کا دل خدا وند اپنے خدا کی طرف کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ دادوں کا دل تھا ‘‘.اسی طرح ۱.سلاطین باب ۱۱ آیت ۹،۱۰ میں لکھا ہے :.’’اور خدا وند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اُس کا دل خدا وند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھاجس نے اُسے دوبار دکھائی دے کر اُس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے پر اُس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خدا وند نے دیا تھا ‘‘.اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کافر کہتے تھے اور آپ کی نسبت بُت پرستی کا الزام لگایا جاتا تھا اور لوگوں میں اُسے پھیلا یا جاتاتھا.عَلٰی مُلْکِ سُلَیْمٰنَ کے الفاظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُس وقت اُن کو کافر کہنے کا عام رواج تھا.دوسری بات جس کا وہاں سے پتہ لگتا ہے یہ ہے کہ جو لوگ بظاہر ان کے ماتحت تھے وہی ان کے خلاف فساد کرتے تھے.حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بقول بائیبل مشرک ہو گئے تھے اس لئے خدا نے اُن کے تین دشمن کھڑے کر دئیے تھے.اوّل : ادومی ہُد ہُد دوم : الیدع کا بیٹا رزون د مشق کا بادشاہ.سوم : یربعام جسے اخیاہ نبی نے سلیمان ؑکی مخالفت پر اُبھارا.چنانچہ ۱.سلاطین باب ۱۱ آیت ۱۴،۲۳و۲۶ میں لکھا ہے :.’’سو خدا نے ادومی ہُد ہُد کو ابھارا کہ سلیمان کا دشمن ہو.‘‘
Page 337
یہ ہُد ہُد ادومی بادشاہوں کی نسل میں سے تھا اور حضرت داؤد ؑ کے وقت مصر بھاگ گیا تھا مگر سلیمان ؑ کے تخت نشین ہونے پر پھر واپس آگیا اور اُس نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں.پھر لکھا ہے: ’’اور خدا نے اِلیدع کے بیٹے رزون کو بھی اُبھارا کہ سلیمان کا مخالف ہو............اور اُس نے اپنے پاس لوگ جمع کر لئے اور جب داؤد نے ضوباہ والوں کو قتل کیا تو وہ ایک فوج کا سردار ہو گیا.اور و ہ دمشق جا کر وہیں رہنے اور دمشق میں سلطنت کرنے لگے.‘‘ ’’اور صرید ہ کے افرائیمی نباط کا بیٹا یر بعام جو سلیمان کا ملازم تھا اور جس کی ماں کا نام جو بیوہ تھی صروعہ تھا اُس نے بھی بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا.‘‘ اِن حوالوں سے ظاہر ہے کہ آپ کے خلاف کئی اندرونی دشمن پیدا ہو گئے تھے.اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی طرف سے آپ کے خلاف خفیہ سازشیں بھی ہوتی تھیں.چنانچہ ۲.تواریخ باب ۱۰ آیت ۲تا۴میں لکھا ہے : ’’اور ایسا ہوا کہ جب نباط کے بیٹے یربعام نے جو مصر میں تھا کہ وہاں سلیمان بادشاہ کے آگے سے نکل بھاگاتھا یہ سُنا تو یربعام مصر سے پھر آیا اور لوگوں نے بھیج کر اُسے بلایا.سو یربعام اور سارے اسرائیلی آئے اور رحبعام سے ہمکلام ہوئے اور بولے کہ تیرے باپ نے ہم پر بھاری جؤا رکھا.سو اب تو اس سنگین خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا کچھ ہلکا کر تو ہم تیری خدمت کریں گے‘‘.اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان ؑ کی وفات کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے آپ کے خطرناک دشمن یربعام کو مصر سے بُلا بھیجا اور آپ کے بیٹے کے تخت نشین ہونے سے پہلے ہی اس سے بعض مطالبات منظور کروانے چاہے اور اپنی اطاعت کو اُن مطالبات کی منظوری کے ساتھ مشروط قرار دیا.بائیبل سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اُن میں خفیہ علامتیں بھی مقرر تھیں.چنانچہ ۱.سلاطین باب ۱۱ آیت ۲۹ تا ۳۲ میں لکھا ہے :.’’اور ایسا ہو اکہ یربعام ایک بار یروشلم سے باہر گیا.اس وقت سیلانی اخیاہ نبی نے اُسے راہ میں پایا.اور وہ ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے تھا.یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے.سو اخیاہ نے اُس نئی
Page 339
تھا.لیکن اُس وقت اُن کے سردار اور لیڈر خدا تعالیٰ کے دو نبی تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اُن کی رہائی کے لئے کوشش کر رہے تھے.اور اُن کا کام بنی اسرائیل کے دشمنوں کو توڑنا اور پھاڑنا تھا.یہ جن لوگوں کو اس مقصد کے لئے اپنے ساتھ ملاتے تھےانہیں کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہیں.ہمارے ذریعہ سے نیکوں اور بدوں میں فرق کیا جائے گا اِس لئے ہماری بات کا انکار نہ کر نا کہ یہ کفر ہے اور وہ اپنے اس ارادہ اور سکیم سے عورتوں کو آگا ہ نہ کرتے تھے اور نہ اُن کو اپنے ساتھ ملاتے تھے یہ ایک قدیم رسم ہے جو اکثر خفیہ سوسائٹیوں میں چلی آتی ہے کہ وہ عورتوں کو اپنے اندر شامل نہیں کرتیں.بنی اسرائیل اور اُن کے وہ نبی جن کا نام اِس آیت میں ہاروت وماروت رکھا گیا ہے اپنی اِن خفیہ تدابیر سے صرف ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ان کے خلاف کوشش کرو اور انہیں نقصان پہنچاؤ.پس اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ بابل میں کیا واقعہ ہوا تھا ؟ بابل کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چند سو سال بعد بابل کا بادشاہ بخت نصر یہودیوں کو یروشلم سے پکڑ کر اور انہیں قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا.یہ بارہ قبیلے تھے جن میں سے دس کو وہ قید کر کے لے گیا اور دو۲ کو چھوڑ گیا(۲.سلاطین باب ۲۵ آیت ۱ تا ۱۳).(یہ دس قبیلے پھیل کر کشمیر وغیرہ کی طرف آگئے ) بنی اسرائیل کے جلاوطن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یرمیاہ نبی نے یہ خبر دی تھی کہ اگر تم سبت کا احترام نہ کرو گے تو تم پر تباہی آجائے گی(یرمیاہ باب ۱۷ آیت ۲۷).چنانچہ اس کی وجہ سے وہ قید ہو کر بابل میںچلے گئے.بابل میں ان کو رہتے ہوئے عرصہ گزر گیا مگر اُن کو نجات نہ ملی.آخر انبیاءِ بنی اسرائیل کے ذریعہ یہ پیشگوئیاں ہوئیں کہ وہ واپس اپنے مرکز میں لے جائے جائیں گے.چنانچہ ان پیشگوئیوں کے مطابق ستر سال کے بعد مَیداورفَارس کاایک بادشاہ بنا جسے خورس اور انگریزی میں سائرس کہتے ہیں.اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کئے کہ اُس کی بابل کے بادشاہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی.چونکہ یہ بادشاہ طاقت پکڑ رہا تھا اس لئے بابل اور دوسری حکومتوں نے اُس پر حملہ کرنا چاہا.مگر یہ اُن سے زیادہ دانا نکلا.اُس نے ان کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا.اور بابل پر بھی حملہ کر دیا.ھاروت و ماروت جو دو نبی تھے انہوں نے اُس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ وہ باہر سے حملہ کرے تو یہود اندر سے اُس کی مدد کریں گے.اور اُس نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ بابل فتح ہونے پر تمہیں واپس یروشلم جانے کی اجازت ہو گی.بلکہ میں تمہیں معبد کی تعمیرکےلئے بہت کچھ مدد بھی دوںگا.چنانچہ اُس نے بابل پر حملہ کیا اور اندر سے یہود نے اُن کی مدد کی اور بابل فتح ہو گیا.اور انہیں واپس اپنے وطن یروشلم جانے کی اجازت ملی.اور عزرا نبی کے زمانہ میں یروشلم پھر آباد ہو ا.اور
Page 340
خورس نے ان کو بہت سا سامان اپنے پاس سے دیا جس میں لکڑی وغیرہ بھی تھی.چنانچہ ہسٹو رینز ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ۲ صفحہ ۱۲۶ میں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ یہود نے خورس سے خفیہ معاہد ہ کیا تھا اور اُس کے حملہ آور ہونے پر اندر سے اُس کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے وہ بابل پر قابض ہو گیا اور اُس کی مدد سے یہود بابل کی قید سے رہا ہو کر واپس اپنے وطن چلے گئے.هَارُوْت و مَارُوْت جن کا اس جگہ ذکر آتا ہے یہ دو نبی ہیں جو جلا وطنی کے زمانہ میں بنی اسرائیل کو واپس لانے پر مقرر ہوئے تھے.اور جنہوں نے مَیداور فَارس کے بادشاہ کی مدد سے آزادی حاصل کی.قرآن کریم نے ان دونوں نبیوں کے صفاتی نام لئے ہیں.یعنی ہاروت اور ماروت.ھاروت جیسا کہ حلِّ لُغَات میں بتایا جا چکا ہے ھرت سے نکلا ہے جس کے معنے پھاڑنے کے ہیں.اور ماروت ، مرت سے نکلا ہے جس کے معنی توڑنے کے ہیں (تاج العروس)پس ھاروت اورماروت کے معنے ہوئے پھاڑنے اور توڑنے والے.چونکہ اُن نبیوں کے سپرد بعض حکومتوں یا جماعتوں کو پھاڑنے اور اُن کی طاقت کو توڑنے کا کام تھا اس لئے اُن کا یہ صفاتی نام رکھا گیا.بائیبل پر غور کرنے سے اندازاً کہا جا سکتا ہے کہ یہ حِجّی نبی اور ذکریا ہ بن عِدّو ہیں.چنانچہ عزرا باب ۵ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہحِـجّی اور ذکریا ہ نبی نے ہی یہود کی آزادی کے لئے کوششیں کیں.اور خورس سے مخفی سمجھوتہ کیا.اور اُس سے آرڈر لکھوائے.پس ہاروت و ماروت حجی اور ذکریاہ نبی ہیں.جنہوں نے خورس سے سمجھوتہ کیا اور اندر سے زور ڈالا جس کی وجہ سے باہر سے خورس نے حملہ کیا اور بابل فتح ہو گیا.ان سب واقعات کی طرف اشارہ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ١ؕ وَ مَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَاۤ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ١ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهٖ١ؕ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِمیں کیا گیا ہے.اب تیسری بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ میں بھی یہود نے کبھی ایسی سازشیں کی تھیں یا نہیں ؟اس غرض کےلئے جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو یہودنے رسول کریم صلی علیہ وآلہٖ وسلم کے خلاف کعب بن اشرف کو بھڑکایا.اور اُس نے آپ ؐ کے خلاف تمام عرب میں مخالفت کی ایک خطرناک آگ بھڑکادی اور پھر اُس نے یہیں تک بس نہ کی بلکہ اپنے اشعار میں اُس نے مسلمان خواتین کی عزت و ناموس پر حملے کرنے شروع کر دئیے.یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے خاندان کی مقدس خواتین کو بھی اُس نے اپنے اوباشانہ حملوں کا نشانہ بنانے سے دریغ نہ کیا (سیرۃ النبی لابن ہشام زیر عنوان مقتل کعب بن اشرف).مگر اس تمام مخالفت کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی حکومت روز بروز بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کا قدم
Page 342
بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایران کے بادشاہ خسرو ثانی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا اُس نے اپنے یمن کے گورنر کے نام آرڈر لکھا کہ ہمیں رپورٹ پہنچی ہے کہ عرب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے.اُسے پکڑ کر ہمارے پاس بھجوادو تاکہ اُسے سزا دی جائے.گورنر یمن نے اپنے دو سفیر آپ کی طرف بھیجے جنہوں نے آکر اطلاع دی کہ ہمیں آپ کی گرفتاری کے لئے بھیجا گیا ہے.اور ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں اور انکار نہ کریں ورنہ ممکن ہے کہ ایران کے بادشاہ کو غصہ آئے اور وہ عرب پر حملہ کر دے.آپؐ نے ان کو دوسرے دن ملنے کے لئے فرمایا.جب وہ دوسرے دن آپؐ سے ملے تو آپؐ نے فرمایا.کہ میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اُس نے آج رات تمہارے خدا وند کو قتل کر وا دیا ہے.انہوں نے نادانی سے سمجھا کہ شاید یہ نہ جانے کے لئے بہانہ بنایا جا رہا ہے اور کہا کہ ہم آپ کی خیر خواہی کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں ورنہ بادشاہ کو غصہ آئے گا.اور ممکن ہے کہ وہ سارے عرب کو ہی تباہ کر دے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.مجھے میرے خدا نے بتایا ہے کہ اُس نے آج رات تمہارے خداوند کو مارڈالا ہے.اس لئے جو کچھ میں نے تمہیں کہاہے وہی اپنے گورنر کو جا کر پیغام دےدو.انہوں نے واپس جا کر گورنر یمن کو یہی بات کہہ دی.گورنر نے کہا ہم چند دن انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے اگر یہ بات درست نکلی تو واقعی وہ سچا نبی ہے ورنہ عرب کی خیر نہیں.کسریٰ سارے عرب کو تباہ کر دے گا.چند دن کے بعد بندرگاہ پر ایک جہاز پہنچا اور اُس میں سے ایک سفیر اُتر کر گورنر یمن کے پاس آیا.اور اُس نے گورنر کو ایک شاہی مکتوب دیا جو سر بمہر تھا.مگر مہر کسی اور بادشاہ کی معلوم ہوتی تھی.خط کو دیکھتے ہی اُس کا ماتھا ٹھنکا.اور اُس نے کہا.عرب کے نبی کی بات سچ معلوم ہوتی ہے.پھر اُس نے خط کھولا تو وہ خسرو کے بیٹے شیرویہ کا خط تھا.جسے انگیریز ی میں سائروس Siroesکہتے ہیں.اس میں لکھا تھا کہ ہمارا باپ سخت ظالم تھا.آخر اس کے ظلموں سے تنگ آکر ہم نے اُسے قتل کر دیا ہے اور اب میں اس کا جانشین ہوں.تم ہمارے نام پر سب لوگوں سے اطاعت کا عہد لو اور یہ بھی یاد رکھو کہ میرے باپ نے جو حکم عرب کے ایک مدعی نبوت کے گرفتار کرنے کے لئے بھیجا تھا وہ بھی ظالمانہ حکم تھا.اُسے بھی ہم منسوخ کرتے ہیں اور جب تک کوئی نیا حکم نہ آئے اس کے متعلق کوئی کارروائی نہ کرو.(طبری جلد ۳ صفحہ ۱۵۸۳،۱۵۸۴ ایڈیشن اوّل) غرض اُسی رات جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہاماً یہ خبر دی گئی تھی کہ کسریٰ کو خدا تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ہے خسروکے بیٹے شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور بیٹے کا اپنے باپ کو مارنا خدا ہی کا مارنا ہے.ورنہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ کوئی اس کا م کے لئے ہاتھ نہیں اُٹھا سکتا.
Page 343
کمزور حصہ سمجھتے ہو اس کے مقابلہ میں دس سورتیں بنا کر پیش کردو تا تمہارے دعویٰ کی آزمائش ہو جائے.مطالبہ میں دس کا عدد اختیار کرنے کی وجہ دس کا عدد اس واسطے استعمال کیا کہ یہ عدد کامل ہے اور چونکہ معترض کے دعویٰ کو رد کرنا تھا اس وجہ سے اس کو دس سورتیں بنانے کو کہا کہ تم کو ایک مثال نہیں دس مثالیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں پس یہاں دس کا لفظ اس لئے نہیں رکھا گیا کہ وہ ایک سورۃ تیار کر سکتے تھے بلکہ اس لئے کہ ان کے اس اعتراض کو دُور کرنے کا بہترین ذریعہ یہی تھا کہ انہیں کئی مواقع اعتراض کے دیئے جاتے.اور سب اس لئے نہیں کہا کہ اس وقت جن معترضوں کا ذکر تھا وہ صرف بعض حصوں کو قابل اعتراض قرار دیتے تھے سب کو نہیں.غرض سورۃ بنی اسرائیل میں چونکہ تکمیل کا دعویٰ تھا اس میں قرآنِ شریف کی مثل کا مطالبہ کیا گیا.اور سورۃ ہود میں چونکہ کفار کے اس اعتراض کا جواب تھا کہ بعض حصے غیرمعقول ہیں اس لئے فرمایا کہ دس ایسے حصے جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور اور قابلِ اعتراض ہوں تم انہی کے مقابل میں کوئی کلام بنا کر پیش کردو تاکہ کفار یہ نہ کہیں کہ ہمیں صرف ایک اعتراض کا حق دیا تھا اور اس کا مقابلہ کرنے میں ہم سے غلطی ہو گئی.تیسرا مقام جس میں قرآن کریم کی بے مثلی کا دعویٰ ہے سورۃ یونس ہے اس میں ایک سورۃ کا مطالبہ کیا ہے جو پہلے دونوں مطالبوں سے کم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ اپنے ایک دعویٰ کے ثبوت کے لئے تھانہ کہ کفار کے اعتراض کی تردید میں.اس جگہ اس آیت سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ سب تصرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اس کے ثبوت میں قرآن کریم کو پیش کر کے اس کے متعلق پانچ دعوے کئے تھے وَ مَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ(یونس:۳۸)یعنی اوّل اس میں ایسی تعلیم ہے جسے انسان بنا ہی نہیں سکتا.دوم پہلی کتب کی اس میں تصدیق ہے.سوم اس میں پہلی کتب کے نامکمل احکام کو مکمل کیا گیا ہے.چہارم یہ کلام بالکل محفوظ اور انسانی دست بُرد سے پاک ہے.پنجم اس کی تعلیم تمام قسم کے انسانوں اور تمام زمانوں کے لئے ہے.اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ سچ نہیں تو پھر تم بھی ایک سورۃ ایسی بنا کر پیش کردو جس میں وہ پانچ باتیں جو بیان کی گئی ہیں ایسے مکمل طو رپر بیان ہوں جیسی کہ اس سورۃ یعنی سورۃ یونس میں بیان کی گئی ہیں لیکن اگر ایک سورۃ کے مقابلہ میں بھی تم کوئی کلام پیش نہ کر سکو تو پھر سمجھ لو کہ سارے کلام میں کس قدر کمالات مخفی ہوں گے اور ان کا بنانا انسانی طاقت سے کس قدر بالا ہو گا! غرضیکہ اس جگہ مِثْلِہٖ سے مراد ان پانچ کمالات کی مثل والا کلام ہے جو سورۃ یونس میں بیان کئے گئے ہیں.سورہ طور میں بیان شدہ تحدّی کا مطلب اب رہی آخری آیت یعنی فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖۤ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ
Page 344
اگر تاریخی شہادت اِسے درست قرار نہ دے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی اور رپورٹیں اُسے پہنچائی گئی تھیں جن کی وجہ سے اُسے طیش آیا تھا.بعض مسلمان مؤرخین نے بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو اس واقعہ کا محرّک بتایا ہے مگر یہ غلط ہے.وہ خط اس امر کا محرک نہیں ہوا بلکہ کسریٰ کے افسر آپ ؐ کے خط سے پہلے ہی آپ ؐ کی گرفتاری کے لئے آپؐ کے پاس پہنچ چکے تھے.چنانچہ زرقانی جلد ۲ صفحہ۲۱۱،۲۱۲پر لکھا ہے کہ لِاَنَّ بَعْثَہٗ لِلْمُلُوْکِ اِنَّمَا کَانَ بَعْدَ الْعَوْدِ مِنْھَافِیْ غُرَّۃِ الْمُحَرَّمِ سَنَۃَ سَبْعٍ کَمَا یَأْ تِیْ (شرح العلامۃ الزرقانی امر الحدیبیۃ و فی ھذہ السنۃ کسفت الشمس المجلد ۳ صفحہ ۲۳۲) یعنی یکم محرم ۷ھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تھے جو اس تاریخ کے لحاظ سے جو ہسٹورینز ہسٹری آف دی ورلڈ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ہجرت کی مقرر کی ہے (جلد ۸ صفحہ ۱۱۸) اس کی تاریخ ۱۲؍اپریل ۶۲۸ءبنتی ہے.اور خسرو ثانی جس نے آپ ؐ کی گرفتاری کا حکم بھیجا تھا وہ ۲۵ ؍فروری ۶۲۸ء کو پکڑا گیا اور ۲۹ ؍فروری ۶۲۸ء کو قتل کیا گیا تھا.(ہسٹو رینز ہسڑی آف دی ورلڈ جلد ۸ صفحہ ۹۵ ) گویا خط اُس کے مارے جانے کے ایک ماہ بارہ دن بعد بھیجا گیا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا خط اس بات کا محرک ہوا تھا کہ خسرو ثانی آپ ؐ کی گرفتاری کا حکم بھیجے.کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا قاصد اس کے قتل کے بعد مدینہ سے مدائن کی طرف جوان دنوں ایران کا پایۂ تخت تھا روانہ ہوا تھا.اگر آپ ؐ کے خط کو اس کا محرک سمجھا جائے تو وہ خط کم از کم تین چار ماہ قبل کا ہونا چاہیے یعنی اس صورت میں آپ کا خط دسمبر ۶۲۷ء کا ہونا چاہیے.حالانکہ آپ ؐ کا خط یکم محرم ۷ھ کو گیاہے جس کی تاریخ حساب کی روـ سے ۴؍مارچ ۶۲۸ء بنتی ہے.پس جو خط آپ ؐ نے ۴؍مارچ ۶۲۸ء کو لکھا وہ اس حکم کا باعث نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا باعث وہی جھوٹی اور غلط رپوٹیں تھیں جو اُسے یہودکی طرف سے پہنچتی تھیں اور جن سے مشتعل ہو کر اس نے یہ ظالمانہ حکم دے دیا اور چونکہ وہ ۲۵ ؍فروری کو پکڑا گیا تھا اور ۲۹؍فروری کو قتل کر دیا گیا اس لئے یہ خط بہر حال اس کی طرف نہیں ہو سکتا بلکہ دوسرے کسریٰ کی طرف تھا جو اس کے قتل کے بعد تخت نشین ہوا.یعنی اس خط کا مخاطب کسریٰ نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا شیرویہ تھا جس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا.جن لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خط کو اِس اشتعال کی وجہ قرار دیا ہے آخر اُن کو بھی تسلیم کر نا پڑا ہے کہ یہ باہر کی تحریک تھی جس سے متأثر ہو کر اُس نے یہ قدم اُٹھایا.یہ تحریک گورنروں کی طرف سے نہیں ہو سکتی کیونکہ عرب کا علاقہ اس کے ساتھ نہ تھا.یہ صرف یہودیوں کی کارروائی تھی.انہوں نے چاہا کہ جس طرح فارس والوں کے ساتھ مل کر ہم نے بابل کو تباہ کیا تھا.اسی طرح دوبارہ ایک بادشاہ
Page 345
کو اکسائیں اور اس کی مدد سے مدینہ والوں کو تباہ کر دیں.یہود کی اس سازش کا سر ولیم میور کو بھی اقرار کرنا پڑا ہے.چنانچہ وہ اپنی کتاب ’’لائف آف محمد ‘‘ ایڈیشن دوم میں لکھتا ہے کہ کسریٰ شاہِ ایران کے افسر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا خط پہنچنے سے پہلے روانہ ہو چکے تھے.اور پھر وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہودی آپ ؐ کے خلاف ایرانی بادشاہ کو اکسایا کرتے تھے.عربوں کی تو ایرانی بادشاہ کے دربار میں کوئی رسائی نہ تھی.عیسائی اس کے دشمن تھے اس لئے وہ بھی اُسے اکسانہ سکتے تھے(لائف آف محمد صفحہ ۳۸۴،۳۸۵).باقی صرف یہودی رہ گئے.اُن کے ذہن میں یہ خیال سمایا ہوا تھا کہ جس طرح فارس کے بادشاہ کی مدد سے بابل والے تباہ ہو گئے تھے اِسی طرح مدینہ بھی ہم فتح کر لیں گے.اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے متواتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کئے گئے.اور آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی.آپؐ پر جس قدر خفیہ حملے کئے گئے ہیں وہ سب یہودیوں ہی کی طرف سے ہوئے ہیں.مثلاً ایک یہودی عورت کی طرف سے آپؐ کو زہر دینا ثابت ہے(سیرۃ النبی لابن ہشام أمر خیبر قصّۃ شاۃ المسومۃ).اسی طرح خفیہ طور پر آپؐ پر ایک بڑی بھاری پتھر کی سِل پھینک کر مارنے کی کوشش بھی یہود ہی کی طرف سے ہوئی تھی (سیرۃ النبی لابن ہشام أمر اجلاء بنی النضیر).یہ لوگ خفیہ سازشوں میں کوئی عارنہ سمجھتے تھے حالانکہ بہادر اور شریف دشمن ایسی باتوں کو عار سمجھتے ہیں اور سامنے آکر مقابلہ کرتے ہیں.مگر یہ لوگ ایسے گرے ہوئے تھے کہ انہوں نے خفیہ طور پر آپؐ کو زہر دینے کی کوشش کی.پھر گھر پر بلا کر مارنے کی کوشش کی اور جب یہ لوگ خود اپنے ارادوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے تو انہوں نے ایران کے بادشاہ کو اُکسا کرآپؐ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی.اس ساری تحقیق سے ثابت ہے کہ (۱) خفیہ سوسائٹیوں کی ابتداء یہود سے ہوئی.(۲) یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں سے تعلق رکھتے تھے.(۳) تین دفعہ انہوں نے خفیہ کوششیں کیں.(i) حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف.(ii) بابل کے خلاف.(iii )او ررسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے خلاف.جب اِن تمام واقعات کی کڑی مل گئی تو ثابت ہو گیا کہ اِن آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں اور خورس اور بابل کے واقعات کی طرف اشارہ ہے.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے متعلق ایرانی
Page 346
بادشاہ کی نالائق حرکت اور یہود کی اُن تمام کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروانے کے لئے کی تھیں.اب ہمیں ایک ایسے واقعہ کا علم ہو گیا جو ان تمام اصولی باتوں کو جو اس آیت سے مستنبط ہوتی ہیں پورا کرتا ہے یعنی وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ والی ایک جماعت ہمیں نظر آگئی جو اس کام کے مشابہ کام کرتی تھی جو شیاطین یعنی بدی کے سرداروں نے ملکِ سلیمان ؑکے خلاف کیا تھا اوراس فعل سے ایک جزئی مشابہت رکھتا تھا جو ملکین یعنی ہاروت وماروت نے بابل میں کیا تھا.معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں زمانوں میں ایک ہی قسم کا فعل ہوا تھا اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام اپنے اندر ایک حد تک اخفا کا پہلو رکھتا تھا.پس ان واقعات کی روشنی میں زیر تفسیر آیات کا ترجمہ کیا جائے تو یہ ہو گا کہ یہ لوگ اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جس کی شیطان صفت لوگ یعنی بدی کے سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانہ میں کیا کرتے تھے اور وہ یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ وہ کافر ہو گیا ہے.بے دین اور مشرک ہو گیا ہے.بتوں کی پرستش کرتا ہے یا ایسی تعلیم دیتا ہے جو دین کے خلاف ہے.اور وہ یہ باتیں لوگوں میں مخفی طور پر مشہور کیا کرتے تھے.وہ آپ کے متعلق یہ بھی مشہورکیا کرتے تھے کہ اس پر بیویوں کا قبضہ ہے اور وہ ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے معبود انِ باطلہ کی پرستش کرتا ہے.حالانکہ وہ خد ا تعالیٰ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے.سلیمان ؑنے ہرگز ایسا نہیں کیا بلکہ یہ شیطان یعنی بدیوں کے سردار خدا تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے تھے.اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے میں نے پہلے بیان نہیں کیا.اور وہ یہ ہے کہ یہاں دو ۲ دعوے کئے گئے تھے.اوّل یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت دشمنوں کی طرف سے کفر کا الزام لگایا جاتا تھا.دوسرے یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ اس کی حکومت کے باغی لوگ خود کافر اور بے ایمان تھے.اس کے متعلق چونکہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ممکن ہے کافر کہنے والے مخالف دیانت داری سے ان کی طرف یہ الزام منسوب کرتے ہوں یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے ان کی مخالفت ہو یا انہوں نے اُن پر الزام تو شرارت سے لگایا ہو مگر ان کی اپنی حالت درست ہو.اس لئے فرمایا کہ الزام لگانے والے مخالف نہ تو دیانت داری سے الزام لگاتے تھے اور نہ ہی کسی غلط فہمی کی وجہ سے اور نہ ہی یہ صورت تھی کہ وہ صر ف شرارت سے الزام لگاتے ہوں اور ان کی ایمانی حالت درست ہو بلکہ وہ اپنی بد عملی اور بے دینی کی وجہ سے ایسا کرتے تھے.یہ مزید دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے.
Page 347
حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کا حوالہ ۱.سلاطین باب ۱۱ آیت ۳،۴،۵،۱۰ ہے جو پہلے گزر چکا پھر آیت ۲۹ تا ۳۳ میں ذکر آتا ہے کہ یربعام جس نے بعد میں بغاوت کر دی تھی اُس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا مقابلہ کر کے دس۱۰ قوموں کو اپنے قبضہ میں کر لیا تھا اور اُس نے خاص طور پر اُن پر الزام لگایا تھا.اس میں یربعام اور اس کے ساتھی اخیاہ کے ذریعہ (جسے نبی کہا گیا ہے ) حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے بُت پرستی کی ہے اور کفر کیا ہے اور شرک میں مبتلا ہوئے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں.یہ الزام لگانے والے خود بت پرست تھے اور بُت پرستی قائم کرنا چاہتے اور اُس میں دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے.اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا اس کا بھی کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں ؟ سو اس کا ثبوت کہ انہوں نے بت پرستی کی ۲.تواریخ باب ۱۳ آیت ۸ سے ملتا ہے کہ یربعام کی حکومت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص ابیاہ کو کھڑا کیا.یہ یربعام کے مقابلہ کےلئے فوج لے کر گیا اور اُس کو مخاطب کر کے کہا :.’’اب تم کو یہ گمان ہے کہ تم خداوند کی بادشاہت جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے اس کا سامنا کر سکو گے.اور تم بڑے انبوہ ہو.اور تمہارے ساتھ وے سنہلے بچھڑے ہیں جنہیں یربعام نے بنایا کہ تمہارے معبود ہوویں ‘‘.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ گوسالہ پرستی کر رہے تھے.اس کا مصر بھاگ جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے.کیونکہ پہلے بھی مصر ہی سے گوسالہ پرستی کی بیماری آئی تھی.معلوم ہوتا ہے کہ مصری کمزور لوگوں کو خرید لیا کرتے تھے.اور اس طرح اپنے معبود کی عظمت کو قائم رکھنا چاہتے تھے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بت پرستی کا الزام لگاتے تھے.حالانکہ وہ خودبت پرست تھے.اگر یہ الزام نہ لگاتے تو اُن کی قوم جو موحّد تھی نہ بھڑکتی اس لئے انہوں نے آپ پر ایسا الزام لگایا جس سے قوم بھڑک اُٹھی اور جب وہ مشتعل ہو گئی تو انہوں نے بُت بنا بنا کر شرک کو رائج کر دیا جس کا بائیبل سے ثبوت ملتا ہے.يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ میں بتایا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو فریب دہ باتیں بتاتے تھے جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا اور باطن کچھ اور.اس کے معنے یہ ہیں کہ اُن کے دل میں شرک تھا.مگر زبان سے توحید کا اظہار کرتے تھے.کیونکہ اس کے بغیر اُن کی قوم ان کے ساتھ نہ مل سکتی تھی.پس وہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم موحّد ہیں اورسلیمان ؑ مشرک ہے.ہم دنیا میں خدا تعالیٰ کی توحید قائم کرنا چاہتے ہیں.منافق بھی ہمیشہ ایسا ہی کیاکرتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہا
Page 348
کرتے ہیں کہ اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ (البقرۃ:۱۲ ) ہم تو اصلاح کی غرض سے کھڑے ہوئے ہیں.اس پر کمزور ایمان والے کہتے ہیں.کہ یہ لوگ بڑی اچھی بات کےلئے کھڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیے.اسی طرح وہ بھی لوگوں کو ملمع سازی کی باتیں سکھایا کرتے تھے.وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَ مَارُوْتَ کے دو طرح معنے ہو سکتے ہیں.(۱) اوّل اس طرح کہ واؤعطف کےلئے ہو.اِس صورت میں مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُکے ساتھ مل کر اِس آیت کے یہ معنے بنتے ہیںکہ اس دوسرے زمانہ میں بھی ویسا ہی کام ہوا ہے.جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا تھا.جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف سوسائٹی بنی تھی اسی طرح ایک اور بادشاہ کے مقابلہ میں بھی اس قسم کی سوسائٹی بنی.مگر فرماتا ہے کہ یہ مشابہت صرف ظاہری ہے ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونے والے کافر تھے اور دوسرے وقت بابل کا بادشاہ کافر تھا اور جو مقابلہ کرر ہے تھے وہ مومن تھے.پہلے زمانہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کےلئے یہ قوم کھڑی ہوئی تھی اور دوسرے زمانہ میں خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ایک کافر بادشاہ کو نقصان پہنچانے کےلئے یہ قوم کھڑی ہوئی تھی.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ کی ہمیشہ یہ تعلیم رہی ہے کہ حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہونا درست نہیں مگر یہاں تو بغاوت قابل تعریف فعل نظر آ تا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر اپنی حکومت کے خلاف کھڑا ہونا بھی درست ہے.یہ اعتراض بظاہر وزنی معلوم ہوتا ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم استثناء رکھتی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ اسلام کی تعلیم میں ہی یہ بات شامل ہے کہ اگر کوئی قوم کسی حکومت کو چھوڑ کرجاناچاہے اور وہ حکومت اُسے جانے نہ دے تو پھر وہ قوم اُس کی مخالفت کر سکتی ہے اور اُسے اجازت ہے کہ وہ چاہے مخفی بغاوت کرے یا کھلم کھلا.وہ اس کا ہر رنگ میـں مقابلہ کر سکتی ہے.اسلام بتاتا ہے کہ جب تم بادشاہ پر خوش نہ ہو اور نا خوشی معمولی ہو تو اُس وقت تک تم انتظار کرو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل تم پر نازل کرے.اور اگر وہ نا خوشی غیر معمولی ہو اور تم انتظار نہ کر سکو.توپھر اس حکومت سے نکل جاؤ.اور اس ملک کو چھوڑ دو.لیکن اگر وہ حکومت تمہیں زبردستی روکے اور وہاں سے جانے نہ دے اور ظلم بھی دُو ر نہ کرے تو اس صورت میں تم اس کا مقابلہ وہاں رہ کر کر سکتے ہو.یہودی لوگ بابل میں قید تھے اور ان کو واپس اپنے وطن جانے کی اجازت نہ تھی.وہ اپنے وطن سے باہر ایک غیر علاقہ میں تھے.اس علاقہ کو چھوڑنے کی انہیں اجازت نہ تھی اور یہ ایک رنگ میں اُن کے مذہب میں دخل اندازی تھی.اس صورت میں ظاہری یا مخفی طور پر بغاوت یا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے.گویا
Page 349
مومن جن باتوں کو برداشت کر سکتا ہے اُن کو تو برداشت کر لیتا ہے مگر جن کو وہ برداشت نہیں کر سکتا اُن کے متعلق وہ صاف طور پر کہہ دیتا ہے کہ ہم ان کی برداشت نہیں کر سکتے.تم ہماری جائیدادیں سنبھالو.ہمارے مال زمینیں اور مکانات لے لو.ہم یہاں سے جاتے ہیں.اور اگر حکومت پھر بھی نہ جانے دے تو اس کا مقابلہ کرنا جائز ہوتا ہے.کیونکہ مومن اس بات کو پیش کر کے کہ ہماری جائدادیں سنبھالو اور ہمیں جانے دو.اپنی طرف سے امن قائم کر دیتا ہے لیکن اگر حکومت پھر بھی نہ جانے دے تو مومنوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ظاہر یا مخفی مقابلہ کریں.کیونکہ اس صورت میں بادشاہ خود امن برباد کرتا ہے اور مقابلہ کی صورت پیدا کرتا ہے.یہاں بھی یہی حالت تھی اور اس حالت میں بادشاہ کا مقابلہ کرنا جائز تھا.کیونکہ نہ تو ان کو واپس اپنے وطن جانے کی اجازت تھی اور نہ وہاں کے لوگوں کو اپنے شہر کے آباد کرنے کی اجازت تھی.آخر اللہ تعالیٰ نے یروشلم کے آباد کرنے کی صورت پیدا کی.چنانچہ عزرا نبی کی کتاب باب۱ آیت۱ تا ۳ میں آتا ہے کہ ’’شاہِ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے برس میں اس خاطر کہ خداوند کا کلام جو یرمیاہ کے مُنہ سے نکلا تھا پورا ہووے.خداوند نے شاہِ فارس خورس کا دل اُبھارا کہ اُس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اور اُسے قلمبند بھی کر کے یوں فرمایا.شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی ساری مملکتیں مجھے بخشیں اور مجھے حکم کیا ہے کہ یروشلم کے بیچ جو یہودہ میں ہے اس کے لئے ایک مسکن بنائوں.پس اس کی ساری قوم میں سے تمہارے درمیان کون کون ہے اس کا خدا اس کے ساتھ ہووے اور وہ یروشلم کو جو شہر یہودہ ہے جاوے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر بناوے کہ وہی خدا ہے جو یروشلم میں ہے.‘‘ یہ وہی خورس ہے جس کی یہود نے مدد کی اور جس نے آکر اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل واپس یروشلم جا سکتے ہیں.پھر یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر سورۂ کہف میں ذوالقرنین کے نام سے آتا ہے.اُسے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ تم بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے دینا.چنانچہ اُس نے اُن سے دوستی قائم کی اور بابل کی حکومت کوشکست دی.بابل کی حکومت سینکڑوں سال سے چلی آتی تھی جس کے مقابلہ میں اُس کی حکومت ایک معمولی ریاست تھی.لیکن خورس کی ترقی دیکھ کر چند حکومتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے کچل دیں.اُسے کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا چنانچہ اُس نے اندرونی طور پر یہودیوں سے سمجھوتہ کر لیا.اور بابل پر حملہ کر دیا.اور خدا تعالیٰ کی تائید سے اُسے فتح کر لیا.اِن واقعات کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہود انہی افعال
Page 350
کی نقل کر رہے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں شیطانی لوگ اُس کی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لئے کیا کرتے تھے.اِسی طرح یہ لوگ اُن باتوں کی بھی پیروی کرنا چاہتے ہیں جو بابل میں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھیں.مگر یہ نہیں سوچتے کہ سلیمان ؑ کا مقابلہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو گندے اور ناپاک تھے اور ہاروت و ماروت سے خفیہ تدابیر سیکھنے والے وہ لوگ تھے جو خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اُس میں حصہ لیتے تھے کیونکہ وہ بابل کے بادشاہ سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لئے کھڑے کئے گئے تھے.وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ہماری بات مان لو اور اندر ہی اندر تیار ہو جائو.جب خورس اور اس کی قوم باہر سے حملہ آور ہو تو تم اندر سے حملہ کر دو.اور وہ یہ بات عورتوں کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ وہ کمزور دل ہوتی ہیں.اور اُن کے متعلق خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں دوسروں کو نہ بتادیں.پس فرمایا کہ تمہاری خفیہ تدابیر اور اُن تدابیر میں بہت بڑا فرق ہے.وہ خدا کے حکم سے لوگوں کو سکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہماری ان باتوں کو ردّ نہ کرنا ورنہ کفر ہو جائے گا.کیا یہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں.اور خدا تعالیٰ کی رضامندی کے لئے کر رہے ہیں.اور کیا یہ اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ جو اُسے ردّ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا.جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں وہ یہ بات نہیں کہہ سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے باغیوں سے مشابہ ہیں نہ کہ بابل کے باغیوں سے.وَ مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍمیں بتایا کہ بابل والے ملکوتی صفت انسان کسی کو نقصان یا ضرر نہیں پہنچاتے تھے.وہ اگر کسی کو نقصان پہنچاتے تھے تو خدا کے الہام کے ذریعہ.اپنے منشا سے ایسا نہیں کرتے تھے.کیا یہ لوگ بھی الہام کے مدعی ہیں؟ کیا یہ بھی خدا کے کسی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں؟ کیا انہیں بھی یہ الہام ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو؟ مگر باوجود اس کے کہ ان کو ایسا کوئی الہام نہیں ہوتا.جب ان کو ان باتوں سے منع کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں اِس بات کی اجازت مل چکی ہے.ہم بابل میں یہی کام کر چکے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ باتیں اور صورتیں اور وجوہات تمہیں یہاں نظر آتی ہیں.تمہارے مقابل پر تو نبی ہے جس کے خلاف تم کام کر رہے ہو اور اُس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام نازل ہوتا ہے.پس تمہاری صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں اور دشمنوں سے مشابہت ہے، جس طرح وہ لوگ اُن کو کافر کہتے تھے اُسی طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو کافر کہتے ہو.اور جس طرح وہ اُن کے خلاف جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلاتے تھے اُسی طرح تم يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ کے ماتحت ہیرپھیر کرتے ہو.مگر بابل میں خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق دو نبیوں کے ماتحت ایسی قوم کے
Page 351
خلاف باتیں کی جاتی تھیں جس کی ہلاکت کا خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا.وہ لوگ الہام کے ماتحت کام کر رہے تھے نہ کہ اپنی طرف سے.وہاں خدا تعالیٰ کے نبیوں کی اتباع میں کام ہو رہا تھا.نہ کہ نبیوں کے خلاف.مگر اب تم چاہتے ہو کہ جس طرح دو ملائکہ صفت انسانوں نے بابل کی حکومت کو تباہ کیا اُسی طرح تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا سلسلہ تباہ کر دو مگر تم ایسا نہیں کر سکتے.کیونکہ تمہاری اُن کے ساتھ مشابہت نہیں بلکہ تمہاری مشابہت سلیمان علیہ السلام کے دشمنوں سے ہے.وہاں بھی تم مخفی سمجھوتے کرتے تھے.مگر آخر تم ہی جلا وطن ہوئے تھے.اسی طرح یہاں بھی ہو گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم کے مقابلہ میں تم ناکام و نامراد رہو گے.مَاۤ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ درحقیقت جملہ مُسْتأنفہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ سلیمان ؑ کے دشمنوں کی بات اور ہے اور ہاروت اور ماروت پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اور ہے.اِن کا یہ دعویٰ کہ ہم ہاروت اور ماروت کے وقت کے لوگوں کے مشابہہ ہیں غلط ہے کیونکہ وہ جو کچھ کرتے تھے الہام الہٰی کے ماتحت کرتے تھے.پس ان کی مشابہت صرف سلیمانؑ کے دشمنوں سے ہی ہے جنہوں نے ایک نبی کی مخالفت کی اور تباہ ہوئے.ہاروت و ماروت کے وقت کے لوگوں کے ساتھ نہیں.(۲)دوسرے معنے اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اِن کی مشابہت دوگروہوں سے ہے.حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں سے اور بابل کے مخالفوں سے.پہلوں سے یہ صحیح معنوں میں مشابہ ہیں اور دوسروں سے صرف سطحی رنگ میں.وَ يَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ اِس میں بتایا کہ یہود کا خیال یہ ہے کہ جس طرح ہم بابل سے فارس اور مید کے بادشاہ کی مدد سے آزاد ہو گئے تھے اُسی طرح اب بھی غیر حکومتوں سے ریشہ دوانیاں کر کے محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے آزاد ہو جائیں گے مگر ایسا نہیں ہو سکتا.ہاروت و ماروت کے وقت اُن کی کامیابی کا باعث یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے.لیکن اب یہ اس کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں.اس لئے اب ان کا سلیمان ؑ کے مخالفوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو کافر کہنا اور کسریٰ سے مخفی سمجھوتہ کرنا اور بیرونی دشمنوں سے مل کر آپ کا مقابلہ کرنا جیسے خیبر کے وقت کیا گیا.اُن کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا.بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو تباہ کرنے کی بجائے یہ یہودی لوگ خود تباہ ہوں گے گویا اس جگہ اُن کے متعلق پیشگوئی کر دی اور انہیں سمجھایا کہ وہ دو وقت خفیہ تدابیر سے مقابلہ کر چکے ہیں.ایک سلیمانؑ کے وقت جبکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے نبی کی مخالفت کی تھی اور دوسرے ہاروت و ماروت کے وقت جبکہ بابل میں انہوں نے آزادی کے حصول کے لئے
Page 352
خور س سے مخفی سمجھوتہ کیا.اب نتائج سے مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ تمہاری کن لوگوں سے مشابہت ہے.پہلی سازش جو ایک نبی کے خلاف کی گئی تھی اُس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی طاقت کمزور ہو گئی اورآہستہ آہستہ ایسے ذلیل ہوئے کہ ایک وقت زبردستی بابل کی طرف جلاوطن کر دیئے گئے.بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے دشمن یر بعام کے لئے بھی سوائے اس کے کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بھاگ کر مصر چلا جائے(۱.سلاطین باب ۱۱ آیت ۴۰).مگر جب اللہ تعالیٰ کے دو نبیوں کے ماتحت انہوں نے وہی تدابیر اختیار کیں تو جلا وطنی سے اپنے وطن واپس آگئے اور ان کا دشمن تباہ ہو گیا.اِن دو مثالوں کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ چونکہ اِس وقت یہود اُسی راستہ پر قدم مار رہے ہیں جس راستہ پر سلیمانؑ کے دشمنوں نے قدم مارا تھا.اس لئے جس طرح سلیمان ؑ کے دشمن جلا وطن کئے گئے تھے.اُسی طرح یہود کو بھی جلا وطن کیاجائے گا.اور اُن کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو گا جیسے سلیمان کے دشمنوں سے ہوا اور یہ اس بات کا ثبوت ہو گا کہ یہ جھوٹے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مخالفوں سے مشابہ ہیں.چنانچہ یہود کو پہلے مدینہ سے جلا وطن کیا جائے گا.پھر خیبر سے بھی نکال دیاجائے گا.حتیّٰ کہ اُن کے ایرانی منصوبوں کی وجہ سے آخر اُن کو عرب سے بھی نکال دیا جائے گا.اورخطہ ءِ عرب ان کے وجود سے بالکل پاک ہو جائے گا.چنانچہ اُن کی کوششوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ کسریٰ بھی ہلاک ہوا اور وہ خود بھی عرب سے جلا وطن کئے گئے.پہلے اُن کو مدینہ سے نکالا گیا.اور یہ لوگ خیبر میں چلے گئے پھر وہاں سے بھی نکالے گئے اور آخر اُن کو عرب کا ملک چھوڑنا پڑا جو بالکل اُس نتیجہ کے مطابق تھا جو حضرت سلیمان ؑ کے خلاف سازش کرنے کا ہوا تھا.وَ لَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍمیں فرمایا کہ یہ لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ نبیوں کی مخالفت اور ایسے گھنائو نے کام کرنے والوں کا اُخروی زندگی کے انعامات میں کوئی بھی حصہ نہیں.مگر اس کے باوجود یہ لوگ اِس قسم کی کارروائیوں سے باز نہیں آتے.چنانچہ ایک دفعہ یہود کے دو ۲ عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے پاس آئے.جب واپس گئے تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اِس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے.اُس نے کہا.معلوم تو سچا ہوتا ہے.دوسرے نے کہا.میرا بھی یہی خیال ہے.اس نے کہاکہ پھر کیا رائے ہے آیا قبول کر لیا جائے؟ اُس نے جواب دیا کہ جب تک جان میں جان ہے ماننا نہیں.دوسرے نے کہا.میرا بھی یہی ارادہ ہے(السیرة النبی لابن ہشام شہادة عن صفیة).اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ دلائل اور سابقہ پیشگوئیوں کی وجہ سے دل میں آپؐ کی سچائی کا اقرار کرتے تھے.مگر زبان سے آپ کی سچائی کو نہیں مانتے تھے.فرماتا ہے کہ ان کے بڑے
Page 353
بڑے لوگ جو شرارت کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اُکساتے ہیں اور وہ اس بات کی بُرائی کو بھی جانتے ہیں کہ ایسے کام اچھا نتیجہ پیدا نہیں کرتے.مگر پھر بھی اِن کاموں سے باز نہیں آتے.وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ.یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ذریعہ سے ہم نے اپنی جانوں کو خرید لیا ہے یعنی انہیں ہلاکت سے بچا لیا ہے.حالانکہ حقیقت اس کے اُلٹ ہے.یہ لوگ اسی کے ذریعہ ہلاک ہوں گے.چنانچہ اِدھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اُن کو سزا دیں گے اور اُدھر ہم آخرت میں انہیں عذاب میں گرفتار کریںگے.لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.انہیں کیا معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اِس قدر طاقت حاصل ہو جائے گی کہ وہ انہیں عرب سے نکال دیں گے.انہیں کیا پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو ایک دن بادشاہت اور حکومت مل جائے گی اور ان کے لئے عرب میں ٹھہرنا بھی مشکل ہو جائے گا.اِس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام خفیہ منصوبوں اور خفیہ سو سائٹیوں کو سخت نا پسند کرتا ہے.اور بابل کا واقعہ ایک استثنائی رنگ رکھتا ہے.کیونکہ وہاں جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہوا.وَ لَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ١ؕ اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو(انہیں معلوم ہو جاتا کہ) اللہ کی طرف سے ملنے والا بدلہ (ہی) لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَؒ۰۰۱۰۴ بہترین(بدلہ) ہے کاش کہ یہ جانتے.تفسیر.فرماتا ہے.اگر یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اُن کو دین و دنیا میںبڑی ترقی ملتی.مگر یہ محض اِس ضد کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں کہ کیوں ہم میں سے کسی پر الہام نازل نہیں کیا گیا.بنو اسمٰعیل کا کیا حق تھا کہ اُن کے ایک فرد پر یہ کلام اُتارا جاتا ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارے لئے کیا کیا عذاب مقدر ہے اور مسلمانوں کو کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں.اور انہیں معلوم ہوتا کہ مستقبل میں حالات کیا شکل اختیار کرنیوالے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر عظمت اور شوکت حاصل کرنی ہے، تو یہ دوڑتے ہوئے آتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتے مگر ان کو مستقبل کا علم نہیں صرف دنیا طلبی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے مخالفت کا شور مچا رہے ہیں.
Page 355
جواب دیا ہے کہ یہ اصل میں کَانَتْ تَتْلُوْا ہے.کانت کو اُڑا کر تَتْلُوْا کر دیا گیا اور الفاظ کو حذف کر دینا عربی زبان کی اُن خصوصیات میں سے ہے جو اُسے دوسری زبانوں سے ممتاز کرتی ہیں(البحر المحیط زیر آیت بقرة :۱۹۲).دوسری زبانوں میں زور دینے کے لئے تنبیہ کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں.لیکن عربی زبان میں صرف حذف سے ہی یہ فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے.چنانچہ کَانَتْ تَتْلُوا سے صرف تَتْلُوْا کر کے یہ مضمون واضح کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے دشمنوں نے بڑے زور سے یہ کام کیا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی اُنہی کے نقشِ قدم پر چل کر اسلام کو مٹانے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں.لیکن اِس کے علاوہ عربی محاورات میں جب کسی لمبی عادت کا ذکر کرنا ہو تو عرب ماضی کی جگہ مضارع استعمال کرتے ہیں جیسے قرآن کریم کی آیت فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ (البقرة:۹۲) میں تَقْتُلُوْنَ سے قَتَلْتُمْ مراد ہے اِسی طرح یہاں جو مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اِس سے یہود کی اُن لمبی سازشوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ سے کرتے چلے آئے تھے اور جو اُن کی ایک رنگ میں طبیعتِ ثانیہ بن چکی تھیں.اِسی لئے ماضی کی بجائے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے.میں نے پچھلے رکوع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کی اُن مخالفتوں کا ذکر کیا ہے جو وہ سابق انبیاء کے مقابلہ میں کرتے چلے آئے ہیں.اور اُن کی بد اعمالیوں کے سِلسلہ کا ذکر کرتے ہوئے بات کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ انہوں نے انبیاء سابقین کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بھی مخالفت کی.اب اِس رکوع میں اُس سلسلہ مخالفت کی بعض اور کڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی جو مخالفت کر رہے ہیں یہ اُن کا ایک دیر ینہ مشغلہ ہے.اور اُن کی یہ مخالفت انہیں خدا تعالیٰ کی مخالفت پر بھی آمادہ کر رہی ہے.چنانچہ آیت نمبر۹۸ میں بتایا کہ یاد رکھو.اس کلام کی دشمنی درحقیقت کلام بھیجنے والے کی دشمنی ہے اور آیت نمبر۹۹ میں بتایا کہ خدا تعالیٰ کی دشمنی گویا تمام اسبابِ روحانی اور جسمانی کی دشمنی ہے جو انسانی ترقی کے ممدو معاون ہیں.اس لئے یہ نہ سمجھو کہ قرآن کریم کا انکار ایک معمولی بات ہے بلکہ یہ خالقِ اسباب اور قوموں کو ترقی و تنزل دینے والے سے جنگ ہے.آیت نمبر۱۰۰ میں بتایا کہ قرآن مجید کا انکار بلا وجہ ہے کیونکہ اس کی صداقت کے زبردست دلائل موجود ہیں.آیت ۱۰۱،۱۰۲ میں بتایا کہ یہ اپنے انبیاء سے عہد کر چکے ہیں کہ ہم آنے والے رسول کو مانیں گے
Page 357
اُنْظُرْنَا.کے معنے ہیں ہماری طرف توجہ کیجئیے.ہمارا انتظار کیجئیے.ہمیں ساتھ شامل کرنے کے لئے ذرا ٹھہر جایئے.(لسان) گویا اُنْظُرْنَا کے بھی وہی معنے ہیں جو رَاعِنَا کے ہیں.مگراس میں وہ شرط نہیں پائی جاتی جو رَاعِنَا میں پائی جاتی ہے.تفسیر.لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا.یہود مسلمانوں کے خلاف دو قسم کی شرارتیں کیا کرتے تھے.اوّل بیرونی اور دوم اندرونی.یہاں اُن کی اُن شرارتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کو محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے برگشتہ کرنے اور اُن کے دلوں میں آپ کا ادب اور احترام کم کرنے کے لئے کیا کرتے تھے.وہ جس طرح اسلام کو تباہ کرنے کے لئے بیرونی لوگوں کو بلکہ حکومتوں تک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا کرتے تھے اسی طرح وہ مسلمانوں کو بھی اسلام سے بدظن کرنے کے لئے کئی قسم کے حیلے اور تدابیر اختیار کرتے.جہاں کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی فوراً اس سے ہمدردی کا اظہار شروع کر دیتے.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آ آکر ایسے الفاظ استعمال کرتے جن کے دو معنے ہوتے تھے ایک اچھے اور ایک بُرےتاکہ مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگیں.اور اس طرح ان کے دلوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا احترام جاتا رہے.اور اُن میں گستاخی اور بے ادبی کی رُوح پیدا ہوجائے.مثلاً تضحیک کرنے کے لئے وہ آپ سے بعض دفعہ کوئی بے معنٰی ساسوال کر دیتے.اور اِس سے اُن کی غرض یہ ہوتی کہ مسلمانوں کے دلوںسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رُعب جاتا رہے اور ان کا اخلاص کم ہو جائے یا شرمندہ کرنے کے لئے عبرانی کے متعلق کوئی سوال کر دیتے یا کوئی حوالہ پوچھ لیتے.حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے فی الحقیقت کسی کی عزت کم ہو جائے.اگر آپ کو پتہ نہ ہوتا تو آپ اعتراف فرما لیتے کہ مجھے اِس کا علم نہیں.حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپؐ نے اپنے چند صحابہؓ کو دیکھا کہ وہ کھجور کے نرومادہ کا آپس میں پیوند کر رہے ہیں.آپؐ نے فرمایا.ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یارسول اللہ! ہم ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں.آپ نے فرمایا.اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہو.انہوں نے یہ سمجھ کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا چھوڑ دیا.لیکن جب درختوں کو پھل نہ آیا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں عرض کیا.کہ آپ کی ہدایت پر ہم نے کھجور کے نرومادہ کو آپس میں ملانا چھوڑ دیا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھل نہیں آیا.آپؐ نے فرمایا.اس قسم کے معاملات کے متعلق تم مجھ سے زیادہ واقف ہو.جب میں تمہیں کوئی دینی حکم دوں تو اُس کی اطاعت تم پر فرض ہے.لیکن اگر کسی دنیوی معاملہ کے متعلق رائے دوں.تو میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو.(مسلم کتاب الفضائل باب وجوب امتثال ما قالہ شرعا دون ماذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم من معایش الدنیاعلی سبیل الرأی)
Page 358
غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا یہ طریق تھا کہ اگر آپ کو کسی بات کا علم نہ ہوتا تو آپ صاف طور پر فرما دیتے کہ مجھے اس کا علم نہیں.لیکن یہود کا مقصد چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ادب اور احترام مسلمانوں کے دلوں سے کم کرنا تھا اِس لئے وہ مجالس میں آ آکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے ایسے سوال کر دیتے جس سے اُن کی یہ غرض ہوتی تھی کہ اگر آپ کو ان کا جواب نہ آئے گا تو آپ شرمندہ ہوںگے.اور مسلمانوں میں بد دلی پیدا ہوگی.مگر اللہ تعالیٰ اپنے الہام کے ذریعہ آپ کو اُن کی شرارتوں سے محفوظ کر دیتا.انہیں شرارتوں میں سے اُن کی ایک شرارت یہ بھی تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن سے اندرونی طور پر ہتک ہوتی تھی.لیکن اگر کوئی روکتا تو وہ کہہ دیتے کہ تم ہماری بات سمجھے نہیں.ہماری تو اس سے یہ غرض نہیں تھی.جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہنے کی بجائے اَلسَّامُ عَلَیْکَ کہہ دیا کرتے تھے.سُننے والا تو سمجھتا کہ انہوں نے سلام کیا ہے مگر اُن کے مد نظر سَام ہوتا جس کے معنے تباہی اور ہلاکت کے ہیں.ایک دفعہ بعض یہودیوں نے ایسا ہی کیا.تو حضرت عائشہؓ بھانپ گئیں اور انہوں نے فوراً کہا عَلَیْکُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَۃُ یعنی تم پر ہی ہلاکت اور تباہی نازل ہو.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا.عائشہ سختی نہ کرو.اللہ تعالیٰ رفق اور نرمی سے کام لینا زیادہ پسند کرتاہے.انہوں نے کہا.یا رسول اللہ! آپ نے سُنا نہیں کہ یہود نے کیا کہا ہے.آپؐ نے فرمایا.کیا تم نے نہیں سُنا کہ میں کیا جواب دیا کرتا ہوں.میں اُن کے اس فقرہ کے جواب میں صرف عَلَیْکُمْ کہہ دیا کرتا ہوں.(بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء علی المشرکین) اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرتے جو گستاخانہ بھی ہوتے اور عامیانہ بھی اور اس سے اُن کا مقصد محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل اور آپ کا استخفاف ہوتا.اللہ تعالیٰ اس آیت میں اُن کے اس اندرونی بغض کی ایک مثال دیتا ہے فرماتا ہے اے مومنو! تم رَاعِنَامت کہو بلکہ اُنْظُرْنَا کہا کرو.حالانکہ رَاعِنَا کے بھی وہی معنے ہیں جو اُنْظُرْنَا کے ہیں.پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ رَاعِنَا نہ کہو بلکہ اُنْظُرْنَا کہو.اس کی وجہ جیسا کہ خود قرآن کریم نے ایک دوسرے مقام پر صراحت کی ہے یہ ہے کہ یہود کا یہ طریق تھا کہ جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپؐ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے رَاعِنَا کا لفظ استعمال کرتے.گو رَاعِنَا کے لُغَتًا یہ معنے ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیں اور ہم سے مہربانی کا سلوک کریں مگر قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہ سیدھی طرح یہ لفظ استعمال
Page 359
نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی زبان کو پیچ دے کر اور اس لفظ کو ایسے رنگ میں بگاڑ کر استعمال کرتے تھے کہ بادی النظر میں تو رَاعِنَا ہی سمجھا جاتا مگر درحقیقت وہ ایک طنزیہ کلام یا گالی بن جاتا.اللہ تعالیٰ اُن کی اس شرارت کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ نساء میں فرماتا ہے.مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَ يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَّ رَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلْسِنَتِهِمْ۠ وَ طَعْنًا فِي الدِّيْنِ١ؕ وَ لَوْ اَنَّهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ اَقْوَمَ(النّسآء :۴۷) یعنی یہودیوں میں سے بعض لوگ خدا تعالیٰ کے الہامات کو اُن کے اصل مقام سے اِدھر اُدھر بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سُنا اور نافرمانی کی.اور کہتے ہیں.ہماری باتیں سن تجھے خدا کا کلام کبھی نہ سنایا جائے.اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رَاعِنَا.یعنی ہمارا لحاظ کر.مگر یہ بات اپنی زبانوں کو پیچ دیتے ہوئے اور دین میں طعن کرتے ہوئے کہتے ہیں.اگر وہ اس شرارت اور فتنہ انگیزی کی بجائے یہ کہتے کہ ہم نے سُنا اور ہم نے اطاعت کی اور کہتے کہ ہماری معروضات سُن اور ہمارا بھی لحاظ رکھ تو یہ امر اُن کے لئے بہت بہتر اور بہت زیادہ درستی ءاخلاق کا موجب ہوتا.مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ میں بکریاں بھی چرائی تھیں اس لئے فتنہ پرداز یہودی ذرا لہجہ بدل کر رَاعِنَا کی بجائے رَاعِیْنَا کہہ دیا کرتے تھے.جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ُ تو تو ہمارا چرواہا ہے اَب تُو نبی کِس طرح بن گیا(البحر المحیط زیر آیت ھٰذا).مگرعلامہ اصفہانی صاحب مفردات لکھتے ہیں کہ کَانَ ذَالِکَ قَوْلًا یَقُوْلُوْنَہٗ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَلٰی سَبِیْلِ التَّھَکُّمِ یَقْصِدُوْنَ بِہٖ رَمْیَہٗ بِالرُّعُوْنَۃِ وَ یُوْھِمُوْنَ اَنَّـھُمْ یَقُوْلُوْنَ رَاعِنَا اَیْ اِحْفَظْنَا، مِنْ قَوْلِھِمْ.رَعُنَ الرَّجُلُ یَرْ عَنُ رَعَنًا فَھُوَ رَعِنٌ وَاَرْعَنُ.(مفردات زیر لفظ رعن )یعنی یہودی رَاعِنَا کا لفظ محض ہنسی اور مذاق کے طور پر استعمال کرتے تھے اور اُن کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حماقت سے متّہم کرنا ہوتا تھا لیکن وہ سُننے والوں کو اس وہم میں بھی مبتلا رکھنا چاہتے تھے کہ وہ رَاعِنَا کا لفظ اِحْفَظْنَا کے معنوں میںا ستعمال کر رہے ہیںحالانکہ وہ رَاعِنَا نہیں بلکہ رَعِنَا کہہ رہے ہوتے تھے.چنانچہ اہل عرب بیو قوف اور احمق انسان کو رَعِنٌ اور اَرْعَنُ کہا کرتے ہیں.اِس نقطہ نگاہ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ لفظ رَعِنٌ سے بھی بن سکتا ہے جس کے معنے احمق خود پسند اور متکبر انسان کے ہیں.منادیٰ ہو کر یہ لفظ رَعِنَا ہوا اور چونکہ وہ لَیًّا بِاَ لْسِنَتِھِمْ کے ماتحت اپنی زبان کو پیچ دے کر یہ لفظ استعمال کرتے تھے تا اُن کی منافقت پر بھی پردہ پڑا رہے اس لئے وہ رَعِنَا کو ایسے رنگ میں ادا کرتے کہ وہ رَاعِنَا بھی سمجھا جاتا.اور چونکہ آخری الف خطاب کے لئے ہے اِس لئے رَعِنَا کے معنے یہ ہوتے کہ اے بیوقوف یا اے دھوکہ خوردہ انسان.
Page 360
گویا بظاہر تو یہی دکھائی دیتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے معزز اور بزرگ ہیں.آپ ہمیں بھی موقع دیں کہ ہم آپ کی باتیں سُنیں.مگر وہ کہتے یہ تھے کہ اس شخص کا دماغ خراب ہو گیا ہے یا یہ بڑا متکبر اور خود پسند انسان ہے.اور اگر انہیں کہا جاتا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو تو وہ فوراً کہہ دیتے کہ ہم نے رَاعِنَا کہا ہے اور آپس میں اشارے کر کے خوش ہوتے کہ دیکھو ہم نے انہیں کیسا بیوقوف بنایا ہے.مگر میرے نزدیک ایک اور وجہ بھی ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کو رَاعِنَا کہنے سے روکا گیا ہے.اور وہ وجہ یہ ہے کہ رَاعِ باب مفاعلہ سے امر کا صیغہ ہے اور اس باب میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ تم مقابل میں ایک بات کرو گے تب ہم تمہارے لئے ایسا کریں گے.پس رَاعِنَا میں یہ مفہوم پایا جاتاہے کہ آپ ہماری رعایت مدنظر رکھیںگے تب ہم بھی آپ کی رعایت ملحوظ رکھیں گے ورنہ نہیں.مگراُنْظُرْنَا کے صرف یہی معنے ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیے یا ہماری طرف نظر عنایت کیجئے.پس رَاعِنَاکے معنے اگرچہ عام محاورہ میں یہی ہیں کہ آپ ہماری رعایت رکھیں.لیکن اس لفظ کے مادہ میں چونکہ بے ادبی کا مفہوم پایا جاتا ہے.اور کسی بڑے آدمی کو جس کا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے یہ کہنا کہ ہم آپ کی رعایت اور ادب صرف اُسی صورت میں کریںگے جب آپ بھی ہماری رعایت رکھیں گے ایک سخت بے ادبی کا کلام ہے.اور یہ ایک قسم کا سودا بن جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی شان اور عظمت کے منافی تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے مخالفت فرمائی اور اسی مفہوم کو ایسے لفظ میں ادا کرنے کا حکم دیا جس میں بے ادبی کا کوئی احتمال نہیں.غرض میرے نزدیک مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے اِس لئے نہیں روکا گیا کہ اُن کی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو.کیونکہ اگر نیّت نہ ہو تو مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.بلکہ اِس لئے روکا گیا ہے.کہ رَاعِ مُرَاعَاۃٌ سے ہے.جس کے معنے یہ ہیںکہ تو میری رعایت کر تو میں تیری رعایت کرو ںگا.جیسے قَاتَلَ کے معنے ہیں یہ اُس سے لڑا اور وہ اِس سے لڑا.اور بَاھَلَ کے معنے ہیں.اُس نے اِس پر لعنت کی اور اِس نے اُس پر.اِسی طرح اگرچہ رَاعِنَا کے عام استعمال میں یہی معنے لئے جاتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کریں مگر لغت میں اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ تم ہماری رعایت کروتب ہم تمہاری رعایت کریں گے اور اس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی ہے.یہودیوں کا منشاء تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ بار بار استعمال کریں تا اُن سے سُن کر مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگ جائیں.اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ادب و احترام آہستہ آہستہ اُن کے دلوں سے دور ہو جائے.اِس بدی کا سدِّ باب کرنے کیلئے خدا تعالیٰ نے سختی سے حکم دے دیا کہ کوئی
Page 361
غرض میرے نزدیک مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے اِس لئے نہیں روکا گیا کہ اُن کی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو.کیونکہ اگر نیّت نہ ہو تو مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.بلکہ اِس لئے روکا گیا ہے.کہ رَاعِ مُرَاعَاۃٌ سے ہے.جس کے معنے یہ ہیںکہ تو میری رعایت کر تو میں تیری رعایت کرو ںگا.جیسے قَاتَلَ کے معنے ہیں یہ اُس سے لڑا اور وہ اِس سے لڑا.اور بَاھَلَ کے معنے ہیں.اُس نے اِس پر لعنت کی اور اِس نے اُس پر.اِسی طرح اگرچہ رَاعِنَا کے عام استعمال میں یہی معنے لئے جاتے تھے کہ آپ ہماری رعایت کریں مگر لغت میں اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ تم ہماری رعایت کروتب ہم تمہاری رعایت کریں گے اور اس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی ہے.یہودیوں کا منشاء تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ بار بار استعمال کریں تا اُن سے سُن کر مسلمان بھی ان الفاظ کو استعمال کرنے لگ جائیں.اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ادب و احترام آہستہ آہستہ اُن کے دلوں سے دور ہو جائے.اِس بدی کا سدِّ باب کرنے کیلئے خدا تعالیٰ نے سختی سے حکم دے دیا کہ کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے متعلق یہ لفظ استعمال نہ کرے.اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے.مسلمانوں میںجو تباہی اور خرابی پیدا ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے.کہ انہوں نے ادب اور احترام کے الفاظ گندے معنوں میں استعمال کرنے شروع کر دئیے.ان کی حکومتیں مٹ گئیں.سلطنتیں بر باد ہو گئیں صرف اس لئے کہ اُن کے نزدیک بادشاہ کے معنے بیوقوف کے ہو گئے.جہاں بادشاہ بیوقوف کو کہا جائے گا وہاں بادشاہ کا ادب کہاں رہےگا.اور جب بادشاہ کا ادب مٹ گیا تو حکومت بھی تباہ ہو گئی.اسی طرح علماء اور بزرگوں کا ادب مسلمانوں کے دلوں سے اس طرح اُٹھا کہ حضرت کا لفظ جو اُن کے متعلق استعمال ہوتا تھا وہی لفظ شریروں اور بدمعاشوں کے متعلق بھی استعمال کرنے لگ گئے.اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کا ادب مٹ گیا اور اُن کی بے ادبی شروع ہو گئی.اسی طرح دیکھو.اللہ تعالیٰ کے لفظ کی بے ادبی سے مسلمانوں پر کس طرح تباہی اور بربادی آئی ہے.جب کسی کے پاس کچھ نہ رہے تو کہتے ہیں اب تو اللہ ہی اللہ ہے.یعنی ان کے نزدیک اللہ کے معنے صفر کے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اللہ اُن کے مدِّنظر ہے.یا حضرت ابوبکرؓ والا اللہ ان کے ذہن میں ہے جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبکہ وہ اپنا سارا مال خدا کی راہ میں دینے کے لئے لے آئے تھے پوچھا تھا کہ آپ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا اللہ (ترمذی ابواب المناقب ابوبکر ؓ).یہ بالکل اَوررنگ تھا لیکن مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ہی اللہ ہے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں رہا.غرض اس رنگ میں اللہ کے لفظ کے استعمال کا یہ نتیجہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے خدا تعالیٰ پر ایمان اُٹھ گیا اوراُن میں دہریت آگئی.پس اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو کہ ادب اور احترام کے الفاظ کبھی گندی اوربری جگہ استعمال نہیں کرنے چاہئیںورنہ قابل احترام چیزوں کا ادب بھی اُٹھ جائے گا.اور اس کا نتیجہ سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہو گا.اسی طرح آیت ،معجزہ، کرامت،نبی ،رسول،شہید وغیرہ تما م الفاظ تمہارے نزدیک بڑے معزز و مکرم ہونے چاہئیں.ورنہ اگر ان الفاظ کا ادب اٹھ گیا تو پھر ان لوگوں کا ادب بھی اُٹھ جائے گا جن کے متعلق یہ الفاظ استعمال کئے جاتے ہیں اور اس طرح اباحت اور بے دینی پیدا ہو جائے گی.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اَلطَّرِ یْقَۃُ کُلُّھَااَدَبٌ.یعنی روحانیت کی تمام تر بنیاد ادب پر ہے (ملفوظات جلد سوم صفحہ ۴۵۵).اگر ادب ملحوظ نہ رکھا جائے یا ایسے الفاظ استعمال کر لئے جائیں جو ذومعنین ہوں تو بعض دفعہ اس کا نہایت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے.انشا ء اللہ خان انشاء ایک بہت بڑے شاعر تھے.اور ہمیشہ اس امر کی کوشش کیا کرتے تھے کہ بادشاہ کی
Page 362
تعریف میں دوسروں سے بڑھ کر بات کہیں.ایک دن دربار میں بادشاہ کی تعریف ہونے لگی.تو کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے بادشاہ بڑے نجیب ہیں.انشاء اللہ خان نے فوراً کہا.نجیب کیا حضور تو اَنْـجَبہیں.اَب اَنْـجَب کے ایک معنے تو زیادہ شریف کے ہیں.مگر ساتھ ہی اِس کے ایک معنے لونڈی زادہ کے بھی ہیں.اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ تھا بھی لونڈی زادہ.تمام دربار میں سناٹا چھا گیا.اور سب کی توجہ لونڈی زادہ والے مفہوم کی طرف پھر گئی.بادشاہ کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی.اور انشا ء اللہ خان کو اُس نے قید کر دیا اورآخر اسی قید میں انہیں جنون ہو گیا اور وہ مر گئے (تاریخ ادب اردو باب ۷ صفحہ ۲۴۷).غرض اللہ تعالیٰ مومنوںکو ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو تم رَاعِنَا مت کہا کرو.بلکہ اُنْظُرنَا کہا کرو.اور ایسے طریق جن سے خدا کے رسول کی بے ادبی ہوتی ہو بچو.لَیًّاکے معنے بھی اِخْفَاءً وَ کِتْمَا نًا کے ہیں.جس میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ رَاعِنَا کا لفظ تو اُن کی زبانوں پر ہوتا تھا مگر اس چیز کو چھپاتے ہوئے جواُن کے مدّ نظر ہوتی تھی وہ اس لفظ کا استعمال کیا کرتے تھے.یعنی ان کی زبانوں پر تو یہی لفظ ہوتا مگر دل میں کچھ اور مطلب ہوتا.اصل میں تو یہ مراد ہوتی کہ تو بڑا احمق اور خود سر انسان ہے مگر جب پوچھا جاتا تو صاف کہہ دیتے کہ ہم تو ان کی نظر عنایت کے طلبگار ہیں.اور رَاعِنَا عرض کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی تھی.اور پھر وہ الگ ہو کر کہا کر تے کہ دیکھا ہم نے نعوذ باللہ اسے اُس کے متبعین میں کیسا ذلیل کیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یہود دلیر ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ماننے والے بھی اُنہیں کچھ وقعت نہیں دیتے.بے شک اُنْظُرنَاکے بھی یہی معنے ہیں کہ ہماری طرف توجہ کیجئے مگر اس میں برابری کا وہ مفہوم نہیں پایا جاتا جو رَاعِنَا میں پایا جاتا ہے.اگر اس کے مفہو م میں بھی یہ بات ہوتی کہ تو توجہ کر تو پھر ہم بھی توجہ کریں گے تو بے شک بے ادبی ہوتی مگراس کایہ مفہوم نہیں ہے.اُ نْظُرنَا کے یہ بھی معنی ہیں کہ ہمارا انتظار کیجئے یا ہمیں مہلت دیجیئے یا ہمیں موقع دیجیئے کہ ہم اپنی معروضات کو پوری طرح پیش کر سکیں.پس یہ ادب کے الفاظ ہیں اور ایسے ہی الفاظ میں اپنی عقیدت کا اظہار کرنا ایک مومن کیلئے ضروری ہوتا ہے.وَاسْمَعُوْ ا میں بتایا کہ ہم نے تمہیں جو یہ حکم دیا ہے.تمہارا فرض ہے کہ تم اسے قبول کرو اور توجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی باتیں سُنا کرو تاکہ تمہیں دوسری دفعہ آپؐ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آوے اور یہ الفاظ تمہیں استعمال ہی نہ کرنے پڑیں.اگر پہلے توجہ نہ کروگے.اور آپؐ کی باتوں کو پورے غور کے ساتھ نہ سنو گے تو تمہیں یہ کہنا پڑیگا کہ ہمیں پھر سمجھائیے اس لئےخدا کے رسول کی باتوں کی طرف تم ایسی توجہ رکھو کہ یہ
Page 363
بات ہی پیدا نہ ہو اور دوسری دفعہ تمہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے.غرض وَاسْمَعُوْا کے دونوں مفہوم ہیں یہ بھی کہ تم ہماری بات مان لو اور یہ بھی کہ تم توجہ سے اس کی باتیں سنو تاکہ یہ صورت ہی پیدا نہ ہو.اگر تم ایسا نہ کرو گے تو یاد رکھو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بن جائیں گی اور تمہارے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی محبت نہیں رہے گی.کیونکہ ظاہر کا باطن پر گہر ا اثر پڑتا ہے.مگر ظاہر ی آداب سے وہ باتیں مراد نہیں جو انسان کو دوسرے کا غلام بنا دیں مثلاً دوسرے کے پاؤں یا گھٹنے کو ہاتھ لگانا.یہ ایک مومن کی انتہائی ذلّت ہے جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں.دوسرے کا ادب بغیر اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے بھی ہو سکتا ہے پس جس بات میں ذلّتِ نفس پائی جائے اُسے کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے اور نہ اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے.وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ میں کفّار سے مراد وہی مفسد اور فتنہ پرداز یہود ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور مسلمانوں میں منافقت کا بیج بونے اور اُن کے دلوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ادب اور احترام کم کرنے کے لئے اس قسم کی شرارتیں کیا کرتے تھے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی حرکات سے باز نہ آئے تو ایک دن انہیں ان کی شرارتوں کا دردناک انجام دیکھنا پڑےگا.مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ لَا الْمُشْرِكِيْنَ اہل کتاب میں سے اور نیز مشرکوں میں سے جن لوگوں نے (ہمارے رسولوں کا ) انکار کیا ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کسی قسم کی خیر (اور برکت) اتاری جائے اور (بھول جاتے ہیںکہ) اللہ تعالیٰ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ١ؕ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۰۰۱۰۶ جسےچاہتاہے اپنی رحمت کے لئے خاص کر لیتا ہے.اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے.تفسیر.فرمایا نہ اہل کتاب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم پر خدا کا فضل نازل ہو اور نہ ہی مشرک.وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ظاہری ادب ترک کر دو.اور تمہارے دلوں میں ان کی وقعت کم ہو جائے اور اس طرح تم میں تفرقہ اور شقاق اور فساد پیدا ہو جائے اور تمہارا اتحاد جس کی
Page 364
وجہ سے تمہیں طاقت حاصل ہے جاتا رہے.اس لئے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے.دشمن کی غرض تو ہنسانا اور تضحیک کا پہلو پید ا کرنا ہوتا ہے.مگر وہ جانتا نہیں کہ اس سے خود اُس کی کمینگی ظاہر ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑتا ہے.وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ.فرماتا ہے.اِن باتوں سے کیا بنتا ہے.خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کر لیتا ہے.اِس وقت اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی رحمت کو مخصوص کر دیا ہے.پس تم چاہے کتنی گالیاں دے لو.خدا کا نبی جیتتا چلا جائے گا.کیونکہ اس کیلئے خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی ہوئی ہے.وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ میں اس طرف توجہ دلائی کہ اُس کی رحمت عام ہے.اس لئے اگر تم ایمان لے آؤتو ہماری رحمت ختم نہیں ہو گئی.اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں بھی ہماری رحمت سے حصہ مل جائے گا.مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ جس کسی پیغام کو بھی ہم منسوخ کر دیں یا بھلوادیں تو اس سے بہتر یا اس جیسا (پیغام ) ہم (دوبارہ دنیا میں)لے آتے مِثْلِهَا١ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۰۰۱۰۷ ہیں.کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر ایک امر پر(جس کا وہ ارادہ کرے) پورا قادر ہے.حَلّ لُغَات.نَسَخَ الشَّیْ ءَ کے معنے ہیں اَزَالَہٗ وَ اَبْطَلَہٗ وَ مَسَخَہٗ.اُس نے کسی چیز کو مٹا دیا.باطل کر دیا اور مسخ کر دیا.(اقرب) نُنْسِھَا.اَنْسَی الرَّجُلُ الشَّیْ ءَ کے معنے ہیں حَمَلَہٗ عَلیٰ نِسْیَانِہٖ.اُسے بھول جانے پر آمادہ کر دیا.(اقرب) پس نُنْسِھَا کے معنے ہیں ہم بھلوادیں اور ذہنوں سے محو کر دیں.اَلْاٰیَۃُ کے معنے ہیں اَلرِّسَالَۃُ.رسالت.تفسیر.یہ آیت ایسی اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں اِس آیت کے متعلق جو غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی تھی اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام صرف اسی کو دُور کرتے تو میرے نزدیک یہی ایک بات آپ کی نبوت اور ماموریت کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوتی.اس کے متعلق مسلمانوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوگئی تھیں اُن کی
Page 365
موجودگی میں اسلام کو سچا مذہب قرار دینا یا اُسے قلبی تسلی اور اطمینان کا موجب سمجھنانا ممکن تھا.کیونکہ اس زمانہ میں اس آیت کے معنے مسلمانوں میں یہ رائج تھے کہ ہم قرآن کریم کی جو آیت بھی منسوخ کر دیں یا اُسے بھلادیں ہم اُس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت لے آتے ہیں.اس آیت کے یہ معنے کر کے وہ اِس سے قرآن کریم میںنسخ کا ثبوت نکالا کرتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن کریم کی بعض آیات یقیناً منسوخ ہو گئی تھیں.اور منسوخ کے وہ یہ معنے لیتے تھے کہ اُن کے احکام کو معطل کر دیا گیا تھا.اور بعض آیات کے متعلق وہ سمجھتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بُھلا دیا تھا.اِس نسخ کے متعلق مسلمانوں کے مختلف نظریات ہیں.اُن کے نزدیک نسخ کی ایک قسم یہ ہے کہ آیت کے معنے تو قائم ہوتے ہیں مگر الفاظ محو کر دیئے جاتے ہیں.گویا ایک آیت معناً تو قرآن کریم میں موجود ہوتی ہے مگر اُس کے الفاظ اس میں نہیں ہوتے.وہ اس کی مثال یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے یہ آیت موجود تھی کہ اَلشَّیْخُ وَالشَّیْخَۃُ اِذَا زَنَیَا فَارْ جُمُوْھُمَا نَکَالًا مِّنَ اللّٰہِ وَاللّٰہُ عَزِیْزٌحَکِیْمٌ.(رُوح المعانی زیر آیت ھذا) یعنی ’’ اگر کوئی بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت زنا کریں تو اُن دونوں کو سنگسار کر دو.یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہے.اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور حکمت والا ہے.‘‘ مگر پھر اسے نکال دیا گیا لیکن اس کا حکم باقی ہے.اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے.دوسری آیت جو اُن کے خیال میں قرآن کریم سے نکال دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ لَوْکَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِیَانِ مِنْ مَّالٍ لَا بْتَغٰی وَادِیًا ثَالِثًا وَلَا یَمْلَأُ جَوْفَہٗ اِلَّا التُّرَابُ (فتح البیان زیر آیت ھذا) یعنی اگر ابن آدم کے پاس مال و دولت سے بھری ہوئی دو ۲ وادیاں بھی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ ایسی ہی اُسے ایک تیسری وادی بھی مل جائے.اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی.دوسری قسم کا نسخ وہ یہ بتاتے ہیں کہ الفاظ آیت تو قائم رکھے جاتے ہیں.مگر اُس کا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے.وہ اس کے ثبوت میں آیت لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (البقرۃ :۲۵۷)کو پیش کرتے ہیں.اس آیت کا حکم اُن کے نزدیک منسوخ ہے مگر الفاظ قائم ہیں.وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کو آیات جہاد نے منسوخ کر دیا ہے.اور اب کفار کو ڈنڈے مار مار کر اسلام میں داخل کرنا جائز ہے.اس کی دوسری مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً١ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَرُ(المجادلۃ :۱۳) یعنی اے مومنو! جب تم رسول سے الگ مشورہ کرنا چاہو تو اپنے مشورہ سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو.یہ تمہارے لئے اچھا ہو گااور تمہارے دل کو پاک کرنیکا موجب ہو گا اُن کے نزدیک اس آیت کے حکم کو اگلی آیت نے منسوخ کر دیا ہے کہ
Page 366
ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ١ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ١ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.(المجادلۃ :۱۴) یعنی کیا تم مشورہ کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ سو چونکہ تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل فرما دیا ہے.پس تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰتیں دو.اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو.اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے.تیسری قسم کا نسخ وہ ہوتا ہے جس میں اُن کے نزدیک آیت کے الفاظ اور معنے دونوں منسوخ ہو جاتے ہیں.اس کی مثال وہ تحویلِ قبلہ کا حکم بتاتے ہیں کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے.لیکن اب اس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں(تفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت ھذا).حالانکہ نہ اس کا حکم موجود ہے اور نہ ہی عملاً اب مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں.غرض یہ تین قسمیں وہ منسوخ آیات کی بتاتے ہیں اور نُنْسِھَا کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اِس سے مراد یہ ہے کہ وہ حصہ ذہنوں سے اُتر جاتا ہے.اِس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ دو صحابہ ؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے ایک سورۃ سیکھی.پھر وہ دونوں ایک رات اسے پڑھنے لگے.مگر اس کا ایک لفظ بھی ان دونوں کو یاد نہ رہا.صبح ہوئی تو وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ وہ سورۃ ہمارے ذہنوں سے اُتر گئی ہے آپ نے فرمایا اِنَّھَا مِمَّا نُسِخَ وَ نُسِیَ یعنی یہ سورۃ بھی منسوخ آیات میں سے تھی جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے منسوخ کر دیا گیا ہے.اور اسے بُھلا دیا گیا ہے.اِسی مضمون کی ایک روایت امام قرطبی نے بھی لکھی ہے.بعض نے نُنْسِھَا کی بجائے نَنْسٰھَا پڑھا ہے.اُن کے نزدیک اِس کے معنے بُھلانے کے نہیں بلکہ یہ ہیں کہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہم اسے قرآن کریم میں ہی رہنے دیتے ہیں بدلتے نہیں.(فتح البیان زیر آیت ھذا) بعض نے اِسے نَنْسٰھَا ہی رکھا ہے.مگر اِس کے معنے نُنْسِھَا کے لئے ہیں.یعنی ہم اسے غائب کر دیتے یا ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں.گویا وہ اِس کے معنے بھول جانے کے لیتے ہیں.مگر ہر شخص معمولی تدبر سے بھی کام لے کر سمجھ سکتا ہے کہ نسخ کا عقیدہ تسلیم کرنے کے بعد قرآن کریم کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا.اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ خدا تعالیٰ نے فلاں آیت کا حکم منسوخ کر کے اُسے قرآن کریم سے نکال دیا ہے تو یہ بات کم ازکم قرآن مجید کے متعلق شبہ پیدا کرنے والی نہ ہوتی.یا جن آیات کو خدا تعالیٰ نے تبدیل کرنا تھا اُن کو قرآن کریم میں درج ہی نہ کیا جاتابلکہ ان کی
Page 367
بجائے جو مستقل حکم دینا تھا صرف اُسے ہی درج کر دیا جاتا تب بھی کوئی بات تھی لیکن اگر اُن کی بجائے کوئی مستقل حکم نہ لانا تھا تو منسوخ شدہ آیات کو قرآن کریم میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے شک یہ درست ہے کہ بعض وقتی احکام منسوخ بھی ہوتے ہیں جیسا کہ صُحفِ ابراہیم ؑ کو صحفِ موسیٰ ؑ نے منسوخ کر دیا اور صحفِ موسیٰ ؑ کو قرآن کریم نے منسوخ کر دیا.پس احکامِ الٰہیہ کا منسوخ ہونا کوئی قابلِ تعجب امر نہیں جو معیوب بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی طرف جو ایک دائمی شریعت ہے اس بات کو منسوب کیا جائے کہ قرآن کریم میں بعض آیات کو درج کر کے پھر انہیں نکال دیا گیا تھاپھر اگر ان کو خارج کر دیا جاتا تب بھی اتنی خطرناک بات نہ تھی.لیکن جب کوئی شخص یہ بات کہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات منسوخ ہیں اور اُن کے الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں اور وہ اس کے ثبوت میں کوئی وحی الٰہی پیش نہ کر سکے بلکہ صرف اپنا قیاس پیش کرے تو اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کا کوئی اعتبار نہیں رہتا.انسانی دماغ کے کئی مدارج ہوتے ہیں.بعض باتوں کو ایک دماغ سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا.اگر اس بات کا فیصلہ انسانی دماغ پر رکھا جائے کہ قرآن مجید میں سے کونسی آیت قابِل عمل ہے اور کونسی منسوخ تو ایک رنگ میں سارا قرآن ہی منسوخ ہو جائے گا.کیونکہ کسی حصّہ کو کوئی نہیں سمجھتا اور کسی کو کوئی.یہی وجہ ہے کہ پانچ آیات سے لے کر گیارہ سوآیات تک منسوخ قرار دی جاتی ہیں.گویا جس کی سمجھ میں پانچ آیتیں نہ آئیں اُس نے پانچ منسوخ کر دیں اور جس کی سمجھ میں سو نہ آئیں اُس نے سو منسوخ کر دیں اور جس کی سمجھ میں ہزار نہ آئیں اُس نے ہزار منسوخ کر دیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر بتایا کہ شروع سے لے کر آخر تک سارا قرآن قابِل عمل ہے بِسْمِ اللہِکی باء سے لے کر وَالنَّاسِ کی س تک قرآن کریم قائم اور قیامت تک کے لئے قابلِ عمل ہے.آپ کے یہ الفاظ مجھے خوب یاد ہیں کہ جب کوئی انسان اس بات کا قائل ہو گا کہ قرآن کریم کے اندر ایسی آیات بھی موجود ہیں جو منسوخ ہیں تو اُسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قرآن کریم پر غور کرے اور سوچے اور اُس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرے.وہ تو کہے گا کہ جب اِس میں ایسی آیات بھی ہیں جو منسوخ ہیں تو میں اِن پر غور کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کروں.ممکن ہے میں جس آیت پر غور کر وں مجھے بعد میں معلوم ہو کہ وہ منسوخ ہے لیکن جو شخص یہ کہے گا کہ یہ کلام تمام کا تمام غیر منسوخ ہے اور اس کا ہر شوشہ تک قابلِ عمل ہے وہ اس کے سمجھنے کی بھی کوشش کرے گا اور اس طرح قرآن اس کی معرفت کی ترقی کا موجب بن جائے گا.اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بڑے بڑے علم والے لوگ پیدا کئے ہیں.مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سارا علمِ قرآن حاصل کر لیا ہے.میں بھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے شمار معارف کھولے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا سارا علم میں نے حاصل کر لیا ہے.اگر
Page 370
تھیں.پس اگر بعض آیتیں یکدم ذہنوں سے محو ہو گئی تھیں تو مسلمانوں میں شور مچ جانا چاہیے تھا.اور چاہیے تھا کہ اس قسم کی بیسیوں روایات ہوتیں.اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ مثلاً حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ وغیرہ کہتے کہ فلاں سورۃ ہمیں یاد تھی مگر پھر اچانک بھول گئی.اِسی طرح اگر لوگوں کو کوئی آیت بھول جاتی تو وہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ سے پوچھتے.وہ کہتے کہ ہمیں بھی بھول گئی ہے.پھر وہ حضرت عثمانؓ سے پوچھتے.وہ کہتے کہ مجھے بھی بُھول گئی ہے.پھر وہ حضرت علیؓ سے پوچھتے.وہ کہتے کہ مجھے بھی بھول گئی ہے.پھر وہ سارے مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے پوچھتے تو آپؐ فرماتے کہ اسے تو فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں اور مجھے بھی یاد نہیں رہی اس طرح تو ایک شور پڑ جانا چاہیے تھا.مگر کہا یہ جاتا ہے کہ صرف دو آدمیوں کو جن کے باپ کا نام بھی معلوم نہیں ایک سورۃ بھول گئی تھی.اور پھر یہ عجیب لطیفہ ہے کہ وہ رات کو اکٹھے لیٹے اور پھر وہ اکٹھے ہی نماز کے لئے اُٹھے اور پھر وہ آیتیں اکٹھی ہی اُن کو بھول گئیں اور صبح کو پھر وہ اکٹھے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پُوچھنے کے لئے گئے.اور پھر یہ بھول اتنی بڑھی کہ اس روایت کے راویوں کے نام بھی لوگ بھول گئے.اور انہیں یاد نہ رہا کہ یہ دو کون آدمی تھے (فتح البیان زیر آیت ھذا).بھول کا یہ لطیفہ کوئی احمق ہی درست تسلیم کر سکتا ہے عقلمند انسان تو اسے بالکل مان نہیں سکتا.جن آیات کے الفاظ منسوخ اور معنے قائم قرار دیئے جاتے ہیں.اُن کے متعلق قابل غور بات یہ ہے کہ جب حکم قائم تھا تو اُن کے الفاظ کو کیوں باطل کیا گیا؟ یہ بات بھی ایسی ہے.جسے کوئی عقل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی.وہ لوگ اس کے ثبوت میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلے رجم کا حکم تھا مگر اب نہیں.لیکن رجم کا حکم منسوخ نہیں ہوا.اسی طرح قرآن کریم میں پہلے یہ آیت ہوا کرتی تھی کہ اَلشَّیْخُ وَالشَّیْخَۃُ اِذَا زَنَیَا فَارْجُمُوْ ھُمَا مگر اب یہ حکم تو قائم ہے مگر الفاظ نکال دیئے گئے ہیں.لیکن سوال یہ ہے کہ الفاظ کیوں نکال دیئے گئے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ حکم تو موجود رہا پھر الفاظ کیوں غائب کر دیئے گئے؟ اِس سے بڑھ کر یہ لطیفہ ہے کہ ایک اور آیت میں یہ ذکر آتا ہے کہ انسان بڑا حریص ہے.اس کے متعلق بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی ہے.حالانکہ وہ ایک واقعہ ہے نہ کہ حکم.اور واقعہ کے متعلق سب مفسرین متفق ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہوا کرتا.چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اَمَّا الْاَخْبَارُ فَـلَایَکُوْنُ فِیْھَا نَا سِخٌ وَلَا مَنْسُوْخٌ یعنی خبروں اور واقعات میں کوئی نسخ نہیں ہوتا.(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا) پس واقعہ والی آیت کو منسوخ کرنے کے کیا معنے؟ اس کے تو یہ معنے بنتے ہیں کہ واقعہ کے متعلق خدا تعالیٰ کو غلطی لگ گئی تھی.حکم کے نسخ کے تو کچھ معنی بھی ہو سکتے
Page 371
ہیں.لیکن غیر حکم میں تو نسخ نہیں ہوتا.پھر وہ کیوں منسوخ ہو گیا؟ غرض یہ باتیں اپنی ذات میں اتنی مضحکہ خیز ہیں کہ کوئی انسان انہیں درست تسلیم نہیں کر سکتا اور پھر منسوخ شدہ آیات کے جو الفاظ بتاتے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں مثلاً اَلشَّیْخُ وَالشَّیْخَۃُ اِذَا زَنَیَافَارْجُمُوْ ھُمَا میں شیخ کے تین معنے ہو سکتے ہیں.اول عالم یا قوم کارئیس اور سردار.دوم شادی شدہ مرد کیونکہ عربی زبان میں شَیْخُ الْمَرْأَۃِ عورت کے خاوند کوکہتے ہیں.سوم بوڑھا اور ضعیف انسان(اقرب).ان معنوں کے لحاظ سے اس فقرہ کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم یا معزز شخص زنا کرے تو اُسے رجم کر دو.چھوٹا کرے تو نہ کرو.دوسرے معنے یہ بنتے ہیں کہ اگر میاں بیوی آپس میں زنا کریں تو ان کو رجم کر دو.کیونکہ شَیْخ اور شَیْخۃ کے معنے اس جگہ میاں بیوی کے بھی لئے جا سکتے ہیں.اِس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ میاں بیوی بھی آپس میں زنا کیا کرتے ہیں.تیسرے معنے یہ بنتے ہیں کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو ناقابل جماع ہوتے ہیں زنا کریں تو اُن کو رجم کردو.غرض تینوں جگہ ناممکنات تسلیم کرنے پڑتے ہیں.یعنی ناقابل جماع مرد اور عورت آپس میں زنا کریں.یا میاں بیوی زنا کریںتو اُن کو رجم کر دو.یا بڑے آدمی زنا کریں تو ان کو رجم کر دو اور اگر چھوٹے کریں تو نہ کرو.غرض جس پہلو سے بھی دیکھا جائے اِسے کوئی شخص قرآنی آیت قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا.پھر سوال یہ ہے کہ یہاں نسخ آیات کے ذکر کا موقع ہی کیا تھا.یہاں تو یہودیوں کی کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی ہی کتاب مانیں گے.پس اگر یہاں نسخ کا ہی ذکر تسلیم کیا جائے تو پھر اس آیت کے یہ معنے ہوںگے کہ یہاں صُحفِ ماضیہ کے نسخ کا ذکر ہے.یعنی تورات وغیرہ کا.مگر مفسّرین کہتے ہیں یہاں قرآن کریم کے نسخ کا ذکر ہے.حالانکہ اِس بات کا پہلے مضمون کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں.پہلے یہ مضمون ہے کہ یہود کہتے ہیں ہم خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کے وارث ہیں ہم اپنے نبیوں کے کلام کو مانتے ہیں.غیر کے کلام کو ماننے کے لئے تیار نہیں.اس پر خدا تعالیٰ نے اُن کے سامنے یہ کیا دلیل پیش کی کہ میرا قرآن بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور بُھلا بھی دیا جاتا ہے اس لئے تم اسے مان لو.حقیقت یہ ہے کہ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا میں قرآن کریم کی آیات کے منسوخ ہونے کا کہیں ذکر نہیں.بلکہ جیسا کہ ترتیب مضمون سے ظاہر ہے پچھلی آیات میں یہود کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کسی قسم کی خیر نازل ہو.اور سب سے بڑی خیر الہام الہٰی ہے.پس اس آیت میں کوئی ایسا ہی ذکر ہو سکتا ہے.جو پچھلی آیات کے مطابق ہو.کوئی مضمون بلا تعلق نکالنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا اور وہ مضمون
Page 373
تمام مخالفین مِل کر بھی اگر اس میں کوئی اختلاف ثابت کرنا چاہیں تو نہیںکر سکتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا شخص جو علمی حیثیت رکھتا ہو یا کوئی مخالفِ جماعت قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنا چاہے تو ہم قرآن کریم سے ہی اُس کا ردّ کر سکتے ہیں.غرض اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گزشتہ زمانوں میں جو پیغام آتے رہے ہیں یا آئندہ آئیں گے ان سب کے متعلق ہمارا ایک قانون جاری ہے اور وہ یہ ہے کہ کبھی تو وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں اور اِس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں مٹا دیا جائے اور اُن کی جگہ ایک نیا نظام آسمان سے اُتارا جائے اور کبھی لوگ انہیں بُھلا دیتے ہیں اور صرف اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نظام لوگوں کی غفلت کی وجہ سے الہٰی نظام کی جگہ قائم ہو گیا ہے اُسے مٹا کر پھر نئے سرے سے وہی پہلا الٰہی نظام قائم کیا جائے.جب الہٰی نظام ہی اپنی ضرورت پوری کر کے مٹائے جانے کے قابل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُس سے بہتر نظام دنیا میں بھجوادیتاہے.اور جب وہ نظام تو صحیح ہو اور لوگوں نے اُسےبھلا دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اُسی پہلے نظام کو بجنسہٖ پھر دنیا میں قائم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں قدرتیں حاصل ہیں.پھر فرماتا ہے اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں.ہم ایک انقلاب عظیم کے پیدا کرنے کے لئے اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں.یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار کو صرف اس امر کا تو غصہ نہ تھا کہ اُن کے خیالات کے خلاف ایک نیا خیال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیش کرتے ہیں.انہیں جس بات کا خطرہ تھا اور جس کا تصوّر کر کے بھی انہیں تکلیف محسوس ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ کہیں قرآن کی حکومت قائم نہ ہو جائے.پس فرمایا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.اے انکار کرنے والو! کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے پس جب اس نے اس بادشاہت کو ایک نئے رنگ میں قائم کر نے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے فیصلہ کے پورا ہونے کو کون روک سکتا ہے.غرض قرآنِ کریم نے مذاہب کے بارہ میں یہ قاعدہ بتایا ہے کہ ہر مذہبی نظام جو قائم کیا جاتا ہے.وہ کچھ عرصہ کے بعد یا تو ناقابلِ عمل ہو جاتا ہے یا لوگ اُسے بھول جاتے ہیں.ناقابل عمل وہ دو طرح ہوتا ہے یا لوگ اُس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں یا زمانہ کے مطابق اُس کی تعلیم نہیں رہتی.یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس تعلیم میں تصرف کر دیتے
Page 375
پس اس آیت میں بتایا گیا کہ کلام الٰہی بھی ایک عرصہ کے بعد یا تو قابل عمل نہیں رہتا یا لوگ اس پر عمل ترک کر دیتے ہیں.قابل عمل نہ رہنا دو ۲ طرح ہوتا ہے.(۱)لوگ اس میں ملاوٹ کر دیتے ہیں (۲)یا زمانہ کے مطابق تعلیم نہیں رہتی.ان دونوں حالتوں کے مقابل پر اللہ تعالیٰ کی بھی دو ۲ سنتیں جاری ہیں.جب کلام نا قابل عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اُسے منسوخ کر دیتا ہے اور اس سے بہتر تعلیم بھیج دیتا ہے کیونکہ زمانہ ترقی کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن جب لوگ عمل ترک کر دیں اور تعلیم محفوظ ہو تو اللہ تعالیٰ اِسی کلام کو دہرا دیتا ہے اور اُس کا مثل نازل کر دیتا ہے یعنی اُسی تعلیم میں ایک نئی زندگی ڈال دیتا ہے اِس آیت کے آخر میں یہ جو فرمایا کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اِس بات پرقادر نہیں.اِن الفاظ سے وہ معنے جو عام طور پر اس آیت کے کئے جاتے ہیںیعنی کہا جاتا ہے کہ اِس آیت میں قرآنی آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے ردّ ہو جاتے ہیں.کیونکہ قرآنی آیات کے منسوخ ہونے سے قدرت الٰہی کے اظہار کا کوئی تعلق نہیں.قدرت کا مفہوم انہی معنوں میںپایا جاتا ہے جو میں نے کئے ہیں.پھریہ جو فرمایا کہ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر کلام جب آئے یا اُسے دوبارہ زندہ کیاجائے وہ ایک انقلاب چاہتا ہے اور یہی امر لوگوں کے خیال میں نا ممکن ہوتاہے.مگر اللہ تعالیٰ ایسے انقلاب پر قادر ہے.خواہ نئے کلام کے ذریعہ سے وہ انقلاب پیدا کر دے خواہ پُرانے کلام ہی کو زندہ کر کے انقلاب پیدا کر دے.یہ معنے جو میں نے کیے ہیں گو جدید ہیں.لیکن آیت کے تمام ٹکڑوں کا حل انہی معنوں کے ساتھ ہوتا ہے.پہلے مفسر اس کے معنے یہ کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں بعض آیتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا اور پھر انہیں منسوخ کر دیتا ہے.مخالف اِن معنوں پر تمسخر کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ وہ آیت نازل کر کے اُسے منسوخ کیوں کرتا ہے.کیا اُسے حکم نازل کرتے وقت یہ علم نہیـں ہوتا کہ یہ حکم لوگوں کے مناسب حال نہیں.دوسرے نسخ سے تو اس کی کمزوری ثابت ہوتی ہے.اس کے بعد اس فقرہ کے کیا معنے کہ اِنَّ اللّٰہَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ.مگر جو معنے میں نے کئے ہیں اُن میں ایک زبردست قدرت کا اظہار ہے.یہ آسان کام نہیں کہ ایک ایسے قانون کو جو لوگوں کے دلوں پر نقش فی الحجر کی طرح جما ہوا ہوا ور جسے چھوڑنے کیلئے وہ کسی صورت میں بھی تیار نہ ہو ں مٹا کر اس کی جگہ ایک نیا قانون قائم کر دیا جائے.یا جبکہ ایک قوم مرگئی ہو اور اپنے قانون کو پسِ پشت ڈال چکی ہو اور اس کی خوبیوں سے غافل ہو گئی ہو پھر اس مردہ قوم میں سے ایک حصہ کو زندہ کر کے اس بھلائی ہوئی تعلیم کی حکومت دُنیا میں قائم کر دی جائے.یقیناً یہ نہایت ہی مشکل کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت پر دلالت کرتا ہے اور اس قدرت کے مزید اظہار کیلئے ہی آیت کے آخر
Page 376
میں یہ الفاظ بڑھادئیے گئے ہیں کہ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ کیا تمہیں علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت خدا ہی کے ہاتھ میں ہے.اور وہ ایسا انقلاب نہایت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے.ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر عیسوی دور وہ پہلا دور ہے جو اس آیت کے دوسرے حصہ کے ماتحت آتا ہے کہ مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَاکہ ہمارے احکام جب لوگوں کے ذہنوںسے اُتر جاتے ہیں تو ہم ویسے ہی احکام پھر اتار دیتے ہیں.یعنی دوبارہ ان کو زندہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس زمانہ میں ایک ایسا نبی آیا جو نئی شریعت نہیں لایا.اور توارت کے بعض مضامین کو اس نے نمایا ں طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا.اسی طرح موجودہ زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے کہ آپ وہ دوسری قسم کا انقلاب پیدا کریں.جسے اس آیت کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے.یعنی کبھی انقلاب اس طرحـ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ کتاب وہی واجب العمل رہتی ہے جو پہلے سے موجود ہو مگرخدا تعالیٰ دوبارہ اس کی مردہ تعلیم کو زندہ کرنے کیلئے ایک انسان اپنی طرف سے کھڑا کر دیتا ہے جو لوگوں کو پھر اس تعلیم پر ازسر نو قائم کرتا ہے.اِسی کی طرف سورۃ جمعہ میں بھی ان الفاظ میـں اشارہ کیا گیا ہے کہ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.وَّ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.(الجمعۃ:۳،۴)یعنی وہ خدا ہی ہے جس نے اُمّیوں میں اپنا رسول بھیجا جو اُن پر آیات الٰہیہ کی تلاوت کرتا ان کا تزکیہ نفس کرتا اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے.اور وہ خدا ہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور پھرآپ کے ذریعہ ایک ایسی جماعت پیدا کرے گاجو صحابہ ؓکے رنگ میں کتاب جاننے والی پاکیزہ نفس اورعلم وحکمت سے واقف ہو گی.گویا وہی کام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نئے سرے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کرنا ہے.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ کلام الٰہی جو اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا قانون نازل کیا جاتا ہے تو کیا قرآن کریم بھی کسی وقت منسوخ ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی نسبت اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر:۱۰)یعنی یقیناًہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے.اور جس تعلیم کی حفاظت کی جائے اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ آئندہ بھی تمام تعلیموں سے افضل رہے گی.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَاۤ اَوْ مِثْلِهَا کہ اگر کوئی کلام منسوخ ہو تب اس سے بہتر لایا
Page 378
بغیر روشنی کے ہیں.کیونکہ تیرا قانون جل گیا.پس کوئی نہیں جانتا اُن چیزوں کو جو تو کرتا ہے اور ان کاموں کو جو شروع ہونے والے ہیں لیکن مجھ پر اگر تیری مہربانی ہے تو روح القدس کو مجھ میں بھیج اور میں لکھوں.جو کچھ کہ دنیا میں ابتداء سے ہوا ہے اور جو کچھ تیرے قانون میں لکھا تھا تاکہ تیری راہ کو پاویں‘‘.اِس پر اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف وحی نازل کی.کہ تُو چالیس دن کی علیحدگی اختیار کر.اور پانچ زودنویس اپنے ساتھ لے میں تیرے دل میں سمجھ کی شمع روشن کرونگا.جو نہ بجھے گی تاوقتیکہ وہ چیزیں پوری نہ ہوـں جو تو لکھنا شروع کر ے گا.چنانچہ حضرت عزرا اور پانچ زود نویس چالیس روز تک دوسروں سے الگ تھلک جا بیٹھے اور انہوں نے الہامی تائید سے ان کتب کو مکمل کیا.( APOCRYPHA 11 - ESDRAS 14) غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تم تو اپنی تعلیموں کو بھی بھول گئے تھے.مگر ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہاری بھولی ہوئی تعلیم کو دوبارہ زندہ کر دیا.لیکن بجائے اس کے کہ تم اس نعمت کی قدر کرتے تم نے اس کا انکار کر کے اپنی تعلیم سے بھی بے اعتنائی کا مظاہر ہ شروع کر دیا.اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ وَ مَا کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ (تعالیٰ) ہی کی ہے ؟ لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ۰۰۱۰۸ اور اللہ (تعالیٰ) کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مدد گار.تفسیر.اس آیت میں اَلَمْ تَعْلَمْ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نہیں بلکہ ہر انسان مراد ہے.چنانچہ اس آیت کا یہ اگلا ٹکڑا کہ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ اَلَمْ تَعْلَمْ میں خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی ذات والا صفات سے نہیں ہے بلکہ فرداً فرداً ہر قاری سے یاہر سامع سے یاہر انسان سے ہے اور اس کے معنے یہ ہیں کہ اے انسان ! یا اے قرآن کے پڑھنے والے یا اے قرآن کریم کے سننے والے کیا تو اِس بات کو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے قبضے میں ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ دنیوی بادشاہتیں بُرے لوگوں سے لے کر قابل ہاتھوں میں دے دیتا ہے.اسی طرح روحانی بادشاہت بھی وہ بعض دفعہ ایک قوم سے لے کر دوسری قوم کو دے دیتا ہے.اور جب آسما ن اور زمین دونوں ایک ہی
Page 379
بادشاہ کے تابع ہیں تو لازماً دونوں میں قانون بھی ایک ہی جاری ہونا چاہیےاور آسمانی قانون کا زمینی قانون پر اور زمینی قانون کا آسمانی قانون پر قیاس کرنا چاہیے.اس آیت میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے.کہ جب تمہارے پاس کوئی نصّ موجود نہ ہو تو تم قانون شرعی کا جو کہ آسمانی قانون ہے قانون قدرت پر جو کہ زمینی قانون ہے قیاس کر لیا کرو.کیونکہ جس طرح آسمانی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے زمینی بادشاہت بھی اُسی کے قبضہ میں ہے اور یہ ممکن نہیں کہ ان دونوں میں کوئی تخالف ہو.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس اصول کو ہمیشہ پیش فرمایا کرتے تھے.کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے.اور قانونِ قدرت اس کا فعل ہے اور یہ نا ممکن ہے کہ دونوں کا بنانے والا تو ایک ہو اور ان میں کوئی اصولی اختلاف پایا جاتا ہو (ملفوظات جلد ۱ صفحہ ۱۴۵).جس طرح زمین میں یہ قانون جاری ہے کہ جب تک کوئی قوم بادشاہت کی ذمہ واریوں کو ادا کرتی رہتی ہے اس کے پاس بادشاہت رہتی ہے اور جب وہ اُن ذمہ واریوں کو اد اکرنے سے قاصر جاتی ہے تو بادشاہت اُس سے چھین لی جاتی ہے.اسی طرح جو مذہب دنیا کی ضروریات کو پورا نہیں کر تے ان کو منسوخ کر دیا جاتا ہے.تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر اعتراض کرنا قانون قدرت کے خلاف ہے.بہر حال کوئی نہ کوئی کلام اس وقت لوگوں کی ہدایت کے لئے آنا چاہیے تھا.اگر یہ شخص نہ آتا تو کوئی اور آجاتا.بہرحال جب پہلی کتابیں اپنی اصلاح کی قابلیت کو کھو بیٹھیں تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کوئی اور کتاب بھیج دیتا.حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی بعثت کے متعلق بھی اِسی قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ع میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا یعنی زمانہ چاہتا تھا کہ کوئی مصلح آئے.پس اگر میں نہ آتا تو کوئی اَور آجاتا.یہی مضمون اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری یہ ناراضگی کہ محمدؐ رسول اللہ کیوںنبی بن گئے بلا وجہ ہے.تم سماوی قانون کا قانون قدرت پر قیاس کرو.قانونِ قدرت یہ ہے کہ جب کوئی چیز مفید نہیں رہتی تو وہ مٹادی جاتی ہے.جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے.کہ اَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْاَرْضِ (الرعد:۱۸)یعنی ہمارایہ قانون ہے کہ جو چیز نفع رساں ہواسے زمین میں قائم رکھا جاتا ہے اور جو چیز نفع مند نہ رہےاُسے مٹا دیا جاتا ہے.اور یہی قانون شریعت کے متعلق بھی ہے کہ جب وہ زمانہ کی غرض کو پورا نہیں کرتی تو اُسے منسوخ کر دیا جاتا ہے.وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ پہلے ہر فرد کو مخاطب کیا تھا اور اسے عام رکھا تھا.اب صرف مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تمہارے لئے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوست اور مدد گار نہیں.جب تم نے
Page 381
آیت کے مطالب کی تفسیر کو لیتا ہوں پہلی آیت میں جنت اور اس دنیا کی نعمتو ںکی مشابہت بیان کی گئی تھی تاکفار کا یہ اعتراض دُور ہو کہ ہمارے پاس تو فلاں فلاں نعمتیں ہیں اور مسلمانوں کے پاس نہیں اور تا مسلمانو ںمیں سے کمزور لوگوں کے ذہن میں بھی جنت کا ایک تمثیلی نقشہ آ جائے.لیکن دوسری طرف قرآن کریم میں صاف طو رپر دوسرے مقامات میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس دنیا کی زندگی اور اُخروی زندگی میں کوئی نسبت ہی نہیں.وہ اعلیٰ روحانی زندگی ہے او ریہ مادہ سے گھری ہوئی زندگی اور کفار اس حقیقت سے واقف تھے.پس اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو دُور کرنا بھی ضروری تھا تا مخالفوں کا اعتراض نہ ہو کہ آخر ایسی دو مغائر باتوں کی مشابہت ظاہر کرنے سے مطلب کیا؟ مچھر کی مثال دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کے مقابلہ کے لئے بیان کی گئی ہے اگر محض ایک ادنیٰ مشابہت کا اظہار مراد ہے تو اللہ تعالیٰ جیسی اعلیٰ ہستی کو ایسی معمولی سی مشابہت کے بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سو اس سوال اور اس کے جواب کو اللہ تعالیٰ اس آیت زیر تفسیر میں بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ بعض لوگ اعتراض کریںگے کہ جنت و دوزخ کا جو یہ تمثیلی حال قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس سے غرض کیا ہے؟ اگر یہ جنت اور دوزخ کا صحیح نقشہ نہیں تو اس کے بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قسم کے اعتراضات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اِن باتوں کے بیان کرنے سے نہیں رُک سکتا جو خواہ تمثیل کے رنگ میں ہوں مگر ہیں مفید اور ان تمثیلوں کے بیان کرنے سے بھی انسانی علم میں ترقی ہوتی ہے اور مومن کچھ نہ کچھ اندازہ اِس بیان سے اپنے ذہنوں میں لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امر جس کا ذکر کیا گیا ہے ضرور اِسی طرح ہو کر رہے گا جس طرح خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے پس اگراس کی پُوری حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں اس کا ایک اندازہ تو ہو گیا جس سے ایمان کو تقویت حاصل ہوئی.یَعْلَمُوْنَ اَنَّہُ الْحَقُّ کی تشریح فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ.یَعْلَمُوْنَ اس جگہ جاننے کے معنوں میں نہیں بلکہ یقین رکھنے کے معنوں میں ہے کیونکہ اس کے دو مفعول آئے ہیں (اور جب عَلِمَ کے دو مفعول ہوں تو اس کے معنے یقین کرنے کے ہوتے ہیں نہ کہ جاننے کے) اور مراد یہ ہے کہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے.حق کے معنے صداقت کے ہیں ایسی صداقت جو بالکل پکیّ اور بغیر ُشبہ کے ہو.یہ مصدر ہے اور مصدر کبھی اسم فاعل او رکبھی اسم مفعول کے معنے بھی دیتا ہے (رَضِیَ ’’شرح کا فیہ‘‘ بحث مصدر) پس اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مومن خوب سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہو کر رہنے والی ہے اور یہ بھی کہ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت شدہ ہے.پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ گو نہایت باریک تشبیہات سے جنت کا ذکر کیا گیا ہے جو درحقیقت اس کا حقیقی
Page 382
اصل بات یہ ہے کہ کوئی سوال زیادتی علم کے لئے ہوتا ہے اور کوئی کج بحثی کے لئے.کوئی بے ادبی کے لئے ہوتا ہے اور کوئی تحقیر و تذلیل کے لئے.غرض ہر سوال الگ رنگ رکھتاہے.معقول انسان کبھی بھی کسی غیر معقول سوال کی دوسرے کو اجازت نہیں دے سکتا.اگر کوئی لڑکا کالج میں پروفیسر کے سامنے کھڑے ہو کر سوال پرسوال کرتا چلا جائے تو وہ لازماً اُسے ڈانٹے گا.اور کہے گا کہ تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو.مگر اس کا یہ مطلب نہیںہو گا کہ پروفیسر اپنی کم علمی کی وجہ سے اسے سوال کرنے سے روک رہا ہے.اسی طرح قرآن کریم نے لغو اور بے ہودہ سوالات کو ناپسند کیا ہے نہ کہ محض سوالات کو چنانچہ سُئِلَ مُوْسیٰ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ جس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے.ان کا نمونہ قرآن کریم کی اس آیت میں دکھایا گیا ہے.کہ يَسْـَٔلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوْسٰۤى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْۤا اَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَةً (النّسآء :۱۵۴)یعنی یہ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو آسمان سے اُن پر ایک کتاب اُتار کرلے آئے.یہ سوال تو انہوں نے پھر بھی کم کیا ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا گیا تھا.اور کہا گیا تھا کہ تُو خدا کو پکڑ کر ہمارے سامنے لے آتب ہم ایمان لائیں گے.اِسی طرح تورات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات بات پر سوال کیا کرتے تھے.مگر صحابہؓ کی یہ حالت تھی کہ وہ کہتے ہیں.ہم اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھے تاکہ ہم بھی سُن لیں(بخاری کتاب العلم باب القراءة والعرض).گویا انہیں اس قدر وقار اور ضبطِ نفس حاصل تھا کہ خود کوئی سوال پوچھنے کی جرأت نہیں کرتے تھے.بہر حال مسلمانوں کو صرف ایسے سوال کرنے سے روکا گیا ہے جو سنّت اللہ اور قانونِ شریعت کے خلاف ہوں یا اپنے اندر گستاخی اور بے ادبی کا رنگ رکھتے ہوں.یا جن سے محض وقت کا ضیاع ہوتا ہو.کوئی حقیقی فائدہ حاصل نہ ہو.مجھے یاد ہے حافظ روشن علی صاحب اور میں دونوں حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا کرتے تھے بعض اور دوست بھی ہمارے اس سبق میں شریک تھے.حافظ صاحب کی عادت تھی کہ وہ بات بات پر بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے اور بڑی سختی سے جرح کرتے تھے.ابھی ہم نے بخاری کا سبق شروع ہی کیا تھا اور صرف دو چار سبق ہی ہوئے تھے کہ حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُن کے سوالوں سے تنگ آگئے.وہ سبق کو چلنے ہی نہیں دیتے تھے.پہلے ایک اعتراض کرتے اور جب حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ اس کا جواب دیتے تو وہ اس جواب پر اعتراض کر دیتے.پھر جواب دیتے تو جواب الجواب پر اعتراض کردیتے.اور اس طرح اُن کے سوالات کاایک لمبا
Page 383
سلسلہ شروع ہو جاتا.کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے.میری عمر اس وقت بیس اکیس سال کی تھی اور طبیعت بھی تیز تھی حافظ صاحب کو سوالات کرتے دیکھا تو میں نے خیال کیا کہ میں کیوں پیچھے رہوں چنانچہ چوتھے دن میں نے بھی سوالات شروع کر دیئے.ایک دن تو حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ چُپ رہے.مگر دوسرے دن جب میں نے بعض سوالات کئے تو آپ نے فرمایا.حافظ صاحب کے لئے سوالات کرنے جائز ہیں تمہارے لئے نہیں.پھر آپ نے فرمایا.دیکھو تم بڑی مدت سے مجھ سے ملنے والے ہو اور تم میری طبیعت سے اچھی طرح واقف ہو.کیا تم کہہ سکتے ہو کہ میں بخیل ہوں یا کوئی علم میرے پاس ایسا ہے جسے میں چھپاکر رکھتا ہوں.میں نے کبھی کوئی بات دوسروں سے چھپاکر نہیں رکھی.جو کچھ آتا ہے وہ بتا دیا کرتا ہوں.اب خواہ تم کتنے اعتراض کرو.میں نے تو بہر حال وہی کچھ کہنا ہے جو میں جانتا ہوں.اس سے زیادہ کچھ بتا نہیں سکتا.اب کسی بات کے متعلق دو۲ ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو جو بات میں نے بتائی ہے وہ معقول ہے تم اُسے سمجھے نہیں.یا پھر جو بات میں نے بتائی ہے وہ غلط ہے اور تمہارا اعتراض درست ہے.اگر جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ غلط ہے.تو یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں بددیانتی سے تم کو دھوکا دینے کے لئے کوئی بات نہیں کہتا.جو کچھ کہتا ہوں اُسے صحیح سمجھتے ہوئے ہی کہتا ہوں.اس صورت میں خواہ تم کتنے اعتراض کرومیں تو وہی کہتا چلا جائوںگا جو میں نے ایک دفعہ کہا.اور اگر میں نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے تو اُس پر اعتراض کرنے کے یہ معنے ہیں کہ وہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی.ایسی حالت میں اگر تم اعتراض کرو گے تو اس سے تمہاری طبیعت میں ضِد پیدا ہو گی.فائدہ کچھ نہیں ہو گا.اِس لئے میری نصیحت یہ ہے کہ تم سوالات نہ کیا کرو بلکہ خود سوچنے اور غور کرنے کی عادت ڈالو.اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو اسے مان لیا کرو اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے دُعا کیا کرو کہ وہ خود تمہیں سمجھائے اور اپنے پاس سے علم عطا فرمائے.اِس نصیحت کے بعد میں نے پھر حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا.کچھ دن گزرے تو آپ نے حافظ صاحب کو بھی ڈانٹ دیا کہ وہ دورانِ سبق میں سوالات نہ کیا کریں.نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے روزانہ بخاری کا آدھ آدھ پارہ پڑھنا شروع کر دیا.بے شک اور علوم بھی ہم پڑھتے تھے لیکن بہر حال آدھ پارہ روزانہ تبھی ختم ہو سکتا ہے جب طالب علم اپنے مُنہ پر مہر لگا لے اور وہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اُستاد سے کچھ نہیں پوچھنا.جو کچھ وہ بتائے گا اُسے سُنتا چلا جائوں گا.بہرحال حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کے اس روکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے خود قرآن کریم پر غور کرنا شروع کر دیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں ابھی طالب علم ہی تھا کہ میں نے خود درس دینا شروع کر دیا.گویا حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوالات سے روک کر میرے ذہن کو اس طرف متوجہ کر دیاکہ مجھے خود بھی قرآن کریم پر غور
Page 384
کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اِسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سوالات سے روک کر اُن کی فطرت اور ذہنیت کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے.بے شک بعض اوقات دوسرے سے بھی کوئی بات پوچھنی پڑتی ہے مگر زیادہ تر خود ہی غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے.میں نے دیکھاہے قرآن کریم میں آدم ؑ کا قصہ آجائے تو لوگ بڑی کثرت سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ اگر سوال کرنے کی بجائے وہ خود سوچیں تو اُن کی تمام مشکلات حل ہو جائیں.اس جگہ صرف ایسے ہی سوالات سے روکا گیا ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں اور اُس کے اندر کفر پیدا کر دیتے ہیں.ورنہ عام سوالات سے جو تحقیق کی غرض سے کئے جائیں اسلام منع نہیں کرتا.وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ.فرماتا ہے.سوال کی اصل غرض تو علم کی زیادتی ہوتی ہے.مگر جو شخص گستاخانہ سوالات کرتا رہتا ہے اور خدا اور اس کے رسول اور اس کے کلام کا ادب ملحوظ نہیں رکھتا.وہ اس گستاخی کے نتیجہ میں اپنے پہلے ایمان کو بھی کھو بیٹھتا ہے اور ایمان میں ترقی کرنے کے بجائے کفر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے.اگر وہ دائرۂ ادب کے اندر رہتے ہوئے نیک نیتی سے سوال کرتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی.پس انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے قلب کا جائزہ لیتا رہے اور لغو بحثوں اور لغو سوالات میں حصہ نہ لیاکرے.حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی جنہوں نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا تھا کہ قادیان سے ایک نُور نکلا ہے مگر میری اولاد اس سے محروم رہی ہے.اُن کے پاس ایک دفعہ کوئی مولوی بحث کے لئے آگیا.انہوں نے فرمایا کہ میں بحث کے لئے تیار ہوں بشرطیکہ مولوی صاحب کی نیت بخیر ہو.معلوم ہوتا ہے وہ مولوی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا تھا اُس نے یہ فقرہ سُنتے ہی کہہ دیا کہ میں آپ سے بحث نہیں کرتا کیونکہ مناظرات میں عموماً نیت بخیر نہیں ہوتی بلکہ صرف اتنا ہی مقصد ہوتا ہے کہ دوسرا فریق ذلیل ہو جائے.اور لوگوں میں واہ وا کا ایک شور مچ جائے.غرض چونکہ بعض سوال حق پانے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ اُن کی غرض محض بحث و مباحثہ لڑائی اور دوسرے کو شرمندہ کرنا ہوتی ہے.اس لئے فرماتا ہے کہ مومنوں کو اس قسم کے سوالات سے بچنا چاہیے.وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اہل کتاب میں سےبہت سے لوگ بعد اس کے کہ حق ان پر خوب کھل چکا ہے اس حسد کی وجہ سے جو ان کی اپنی ہی اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا١ۖۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جانوں سے (پیدا ہوا )ہے چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں.پس تم اس وقت
Page 385
تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ١ۚ فَاعْفُوْا وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ تک کہ اللہ (تعالیٰ) اپنے حکم کو نازل فرمائے انہیں معاف کر و اور (ان سے ) درگذر کرو.بِاَمْرِهٖ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۰۰۱۱۰ اللہ یقیناً ہر ایک امر پر پورا(پورا ) قادر ہے.حَلّ لُغَات.وَدَّ کے معنے چاہنے کے ہیں.اور وَدُوْدٌ بہت محبت کرنے والے کوکہتے ہیں.لَوْ کے معنے کاش کے ہوتے ہیں.اور یہ’’اگر‘‘ کے معنے بھی دیتاہے.اِسی طرح مصدری معنے بھی دیتاہے.یَرُدُّوْنَکُمْ.یہ اَنْ یَّرُدُّوْکُمْ کا قائم مقام ہے.چونکہ اس جگہ دو مفعول آئے ہیں اِس لئے یہ صَیَّرَکُمْ کے معنے دیتا ہے جس کے معنے بنا دینے کے ہیں.کُمْ مفعول اوّل اور کُفَّارًا مفعول ثانی ہے.اور حَسَدًا مفعول لہٗ ہے.عَفْو کے معنے مٹادینے کے ہیں.لیکن جب یہ لفظ کسی مذہبی امر کے متعلق ہو تو اس کے معنے گناہ کو مٹا دینے کے ہوتے ہیں.(اقرب) صَفَحَ کے معنے ہیں’’پہلو پھیر لیا‘‘.جب انسان مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو سامنے آتا ہے.اور اُس کا ناک آنکھ مُنہ نظر آرہا ہوتا ہے.لیکن جب مقابلہ نہ کرنا چاہے تو دوسری طرف چلا جاتا ہے اس لئے اس کے معنے درگزر کرنا.مُنہ پھیر لینا.(المنجد) تفسیر.حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری عمر میں اُن کا پلوٹھا بیٹا اسمٰعیل ؑ ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوا اور اس کے بعد اُن کی پہلی بیوی سارہ کے بطن سے اسحاق ؑ پیدا ہوا(پیدائش باب ۱۶ و ۱۸).سارہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماموں کی بیٹی تھی ان کو خیال تھا کہ میں خاندانی ہوں اور ہاجرہ باہر کی ہے.اِس لئے وہ اپنا درجہ بڑا سمجھتی تھیں.اتفاقاً حضرت اسمعٰیل ؑ جو بچے تھے ایک دفعہ حضرت اسحاق ؑ کی کسی حرکت پر یا کسی اور وجہ سے قہقہہ مار کر ہنس پڑے.حضرت سارہ نے سمجھا کہ اِس نے میری اور میرے بچے کی تحقیر کی ہے اور قہقہہ مارا ہے شاید یہ بھی خیال کیا کہ یہ اس بات پر خوش ہے کہ یہ بڑا بیٹا ہے اور یہ وارث ہو گا اور اسحاق وارث نہیں ہو گا.تب انہوں نے غصہ میں آکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہاکہ اس کو اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دو کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی
Page 386
کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ تیرا بیٹا وارث ہو.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو اِس بات کو بُرا منایا.اور اس کام سے رُکے.مگر خداتعا لیٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو مکہ سے ظاہر کرنا چاہتا تھا اُس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ جو کچھ تیری بیوی سارہ کہتی ہے وہی کر.(پیدائش باب۲۱ آیت۱۲)چنانچہ خدا کے حکم کے ماتحت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعٰیل ؑ کو وادیٔ حرم میں چھوڑ گئے اور سارہ اور اسحاق ؑ کے سپرد کنعان کا علاقہ کر دیا گیا.حضرت اسمعٰیل ؑ کی نسل نے مکہ میں بڑھنا شروع کیا اور وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اسمعٰیل کے گھرانے میں پیدا ہوئے.مگر یہ رقابت یہیں ختم نہیں ہو گئی بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمعٰیل علیہ السلام کی پیدائش پر ان کی ماں سے کہا تھا.اُسی طرح ہوا کہ ’’اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے‘‘.(پیدائش باب۱۶ آیت۱۲) یعنی ایک زمانہ تک اسماعیلی نسل تھوڑی ہو گی اور اسحاق ؑ کی نسل زیادہ ہو گی اور وہ سب کے سب مل کر اسماعیلی سلسلہ کی مخالفت کریںگے.اور کوشش کریں گے کہ وہ کامیاب نہ ہو قرآن مجید نے اس کا یوں ذکر فرمایا ہے کہ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا١ۖۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُُّّ.یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسمعٰیلی نسل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اُسے چھوڑ کر پھر کافر ہو جائیں اور یہ بغض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصور کی وجہ سے نہیں بلکہ اُن کے اپنے دلوں سے پیدا شدہ بغض کی وجہ سے ہے اور رقابت کی وجہ سے ہے.وہ سارہ اور ہاجرہ کی لڑائی کو دو ہزار سال تک لمبا لے جانا چاہتے ہیں.پس اُن کی اس خواہش کی بنیاد کسی جذبۂ خلوص پر نہیں بلکہ اُن کے حسد پر ہے.وہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر تم اُن سے نیکی اور تقویٰ میں بڑھ گئے ہو.پس اب وہ اس کا ازالہ اس رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایمان سے محروم کر دیں.حالانکہ اگر وہ خود ایمان لے آئیں تو وہ بھی مسلمانوں کے دوش بدوش نیکی اور تقویٰ میں ترقی کر سکتے ہیں.مگر اُن کے دلوں میں یہ جلن ہے کہ تم نے مان لیا اور وہ محروم رہ گئے.اور اس حسدا ور بغض کی وجہ سے وہ تمہاری کسی نیکی اور خوبی کو برداشت نہیں کر سکتے.حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ دوسرا مفعول لہٗ بھی ہو سکتا ہے.اِس لحاظ سے اس کے یہ معنے ہوں گے کہ یہ جذبہ خود اُن کے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے.تمہارا کوئی فعل اس کا باعث نہیں.دنیا میں حسد دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو باعث کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے.اور دوسرا وہ جو باعث کے لحاظ سے بھی بُرا ہوتا ہے اور نفس کے لحاظ سے بھی بُرا ہوتا ہے.مثلاً اگر کوئی غیرمسلم مال و دولت میں بڑھ جائے اور کوئی مسلمان اس پر حسد کرے تو یہ حسد اس وجہ
Page 387
سے بھی ہو سکتا ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹے کیونکہ خدا تعالیٰ کفر کو ناپسند کرتا ہے اور اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا نفس اس بات کو برداشت نہ کر سکتا ہو کہ کسی غیر مسلم کو زیادہ دولت مِل جائے اور پھر یہ حسد محض نفسانی بھی ہو سکتا ہے جس میں کسی دینی جذبہ کا دخل نہ ہو.محض دنیوی خواہشات اس کی پشت پر کام کر رہی ہوں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کا حسد مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْہے.یعنی یہ حسد اُن کے اپنے نفسوں کی خرابی اور بُخل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے.اس کا موجب مسلمانوں کا کوئی فعل نہیں.اگر مسلمان ان کو چڑاتے اور اس وجہ سے ان کو غصہ آتا تو پھر حسد کا باعث مسلمان ہوتے لیکن مسلمان تو اُن کی خیر خواہی کرتے اور اُن کی ترقی کی کوشش کرتے ہیں پس اُن کا حسد اُن کے اپنے نفس سے پیدا ہوا ہے.مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ.مسلمانوں کو کافر بنانے کی خواہش دو ۲ وجوہ سے ہو سکتی تھی.اوّل اس وجہ سے کہ اہل کتاب غلطی سے یہ سمجھتے ہوں کہ مسلمانوں کی حالت کفار سے گری ہوئی ہے اِ س لئے بہتر ہے کہ وہ پھر کفر اختیار کر لیں.دوسرے اہل کتاب غلطی سے نہیں بلکہ علیٰ وجہ البصیرت سمجھتے ہوں کہ مسلمانوں کی حالت اہل مکہ کی حالت سے بھی گری ہوئی ہے اور سمجھتے ہوں کہ اگر یہ اس پہلی حالت پر رہتے تو زیادہ بہتر ہوتا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر واقع میں اُن کی یہ خواہش نیک نیتی پر مبنی ہوتی تو اور بات تھی مگر ان کی یہ خواہش اس لئے نہیں کہ مکہ والے اِن سے اچھے ہیں بلکہ یہ لوگ محض حسد کی وجہ سے ایسی خواہش کرتے ہیں.دوسرے یہ خواہش کسی غلط فہمی کی بنا پر نہیں بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ مکہ والوں کی حالت اِن سے ادنیٰ ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے پھر بھی یہ مسلمانوں کو کافر بنا دینے کے درپے ہیں.پس یہ مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں.اس جگہ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ نے واضح کر دیا ہے کہ باوجود اس بات کے جاننے کے کہ اِس مذہب کو فضیلت حاصل ہے پھر بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کفر پھیلے اور ہدایت کا دائرہ زیادہ سے زیادہ تنگ ہو تا چلا جائے.مسلمانوں کے متعلق اہل کتاب کی جس خواہش کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے قرآن کریم کے بعض اور مقامات میں بھی اس کا بیان ہوا ہے.چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.وَدَّتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ١ؕ وَ مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ (آل عمران :۷۰)یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے.حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں.اسی طرح سورہ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ(آل عمران:۱۰۱)کہ اے مومنو! اگر تم ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے کسی فریق کی اطاعت کروگے تو وہ تمہارے ایمان لے
Page 388
آنے کے بعد پھر تمہیں کافر بنادیںگے.فَاعْفُوْا.گناہوں کو تین رنگ میں مٹایا جاتا ہے.اوّل دنیوی نتائج کے لحاظ سے جیسے گناہگار کو جسمانی سزا سے بچالینا.دوم اُخروی نتائج کے لحاظ سے جیسے گنہگار کو شرعی سزا سے بچا لینا.سوم گناہ کے زنگ اور اُس کے سیلان تک کو مٹا دینے کے لحاظ سے.یہ عفو کامل سمجھا جاتا ہے.کیونکہ اس میں دل پر جو گناہ کا زنگ لگ جاتا ہے اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے.چونکہ اس جگہ مسلمان مخاطب ہیں.اس لئے اس جگہ اُخروی شرعی سزا مراد نہیں بلکہ دنیوی سزامراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم ان کو خود سزا دینے کی کوشش نہ کرو.بلکہ عفو سے کام لو.فَاعْفُوْا کی فاء سے ظاہر ہے کہ یہ حکم اہل کتاب کے کسی پہلے فعل کے نتیجہ میں دیا گیا ہے.اور وہ پہلا فعل یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو پھر کافر بنانا چاہتے تھے.پس فَاعْفُوْا کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ یہ لوگ تمہیں دین سے منحرف کرنا چاہتے ہیں اس لیے تم انہیں معاف کر دو کیونکہ معافی کا موجب ہمیشہ کوئی نیکی ہوا کرتی ہے اور نیکی انہوں نے کوئی کی نہیں بلکہ الٹا یہ خطرناک دشمنی کی کہ مسلمانوں کی مرکزیت کو تباہ کر کے پھر انہیں لا مرکزیت کی طرف لے جانے کی کوششیں شروع کردیں.ایسی صورت میں اُن کی کسی نیکی کو اس معافی کا موجب نہیں سمجھا جا سکتا.اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی بلکہ ذکر یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ایک ایک کر کے پھر مرتد کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا کا حکم کیوں دیا گیا؟سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں عَفو اور صَفح سے عفو کی تین مذکورہ بالا قسموں میں سے صرف اوّل قسم مراد ہے.اور مطلب یہ ہے کہ تم انہیں جسمانی سزا دینے کی کوشش نہ کرو.کیونکہ اُن کے اس فعل کی سزا ہم خود انہیں دیںگے.اور عَفو کے ساتھ صَفح کو جس کے معنے منہ پھیرلینے کے ہیں اس لئے شامل کیا گیا ہے کہ نہ صرف اُن کو کوئی سزا نہ دو بلکہ یوں بھی سختی سے پیش نہ آئو.بلکہ اُن سے اعراض کرو.اسی لئے فرمایا کہحَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ.یعنی تم اُن سے درگزر کرو.یہاں تک کہ اُن کے لئے خدا تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو جائے.یا اُن پر عذاب نازل ہو جائے.اس جگہ اَمر سے مراد جہاد کاحکم نہیں بلکہ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نافذ کرے.یعنی مختلف عذابوں سے انہیں ہلاک کرے.آخر جو لوگ جسمانی، قلبی، دماغی اور روحانی لحاظ سے اِتنے بڑے جرائم کے مرتکب ہوجائیں اور یہ جاننے کے باوجو کہ کفّار اُن سے ادنیٰ ہیں پھر بھی مسلمانوں کو کفر کی طرف لوٹانا چاہیں اور پھر یہ لوگ حاسد بھی ہوں اور حسد کا موجب ان کے اپنے نفسوں کی کمینگی اور گندگی ہو تو اُن کو سوائے خدا کے اور کون سزا دے سکتا ہے.انسان صرف جسمانی سزا دے سکتا ہے.وہ دماغی فکری، قلبی اور رُوحانی سزا کسی کو نہیں دے سکتا.یہ قطعی اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے کیونکہ
Page 389
انسان کے دماغ ،قلب، جسم اوررُوح پر اُسی کا قبضہ ہے اس لئے فرمایا کہ ان پر ہم چوٹ لگا ئیںگے تم انہیں ہمارے لئے چھوڑ دو.ہم ان کے دماغ پر بھی چوٹ لگائیں گے.ہم ان کے فکر پر بھی چوٹ لگائیں گے.ہم ان کے قلب پر بھی چوٹ لگائیںگے.ہم ان کی رُوح پر بھی چوٹ لگائیں گے.چنانچہ ایسا ہی ہوا.یہود مدینہ نے زبانی باتوں سے گزر کر سیاسی طریقوں سے مسلمانوں کو دکھ پہنچانا چاہا اور قتل تک کی سازشیں کیں.تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن سے جنگ کی اجازت ہوئی اور مسلمانوں کی قلیل جماعت کے ہاتھوں یہود سخت ذلیل اور رُسوا ہوئے.وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ١ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ اور نماز کو (مطابق شرائط) قائم رکھو اور زکوٰۃادا کرو اور (یاد رکھو کہ ) جو نیکی بھی تم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا اپنی ذات کے لئے آگے بھیجوگےتم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے.اللہ (تعالیٰ) تمہارے تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۰۰۱۱۱ اعمال کو یقیناً دیکھ رہا ہے.تفسیر.خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم ان لوگوں کو سزا نہ دو بلکہ اسے ہم پر چھوڑ دو چونکہ مسلمانوں پر گراں گزر سکتا تھا.اس لئے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تمہیں دشمن کے مقابلہ میں اپنی بے بسی کو دیکھ کر غصہ آئے اور تمہارے لئے صبر کرنا مشکل ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھک جائو اور نمازوں میں ہم سے دُعائیں مانگو.کہ اے اللہ تو خود ان کو ہدایت دے اور اگر ان کے لئے ہدایت مقدر نہیں تو ہمیں ان کے ضر ر سے محفوظ رکھ.اور انہیں ہمارے راستہ سے ہٹا دے.وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ.اور دوسرا علاج یہ ہے کہ تم زکوٰۃ کے ذریعہ غرباء کی مدد کرو.یتامیٰ و مساکین اور بیوگان کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش آئو.قوم کے کمزور طبقہ کو اونچا کرنے کی کوشش کرو.اور وہ لوگ جو کفار میں سے نیک نیتی کے ساتھ مذہب کی تحقیق کرنا چاہیںاُنکو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرو.اس میں اشارہ فرما دیا کہ ان لوگوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے ہم بچانا چاہتے ہیں.ایسے لوگوں کو حسنِ سلوک کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لو.جب وہ ان
Page 391
رہی ہوں.اور اُن بدیوں کے مقابلہ کے لئے تیار رہے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہوں.اسی طرح صبر کے ایک معنے یہ ہیں کہ انسان استقلال کے ساتھ اُن نیکیوں پر قائم رہے جو اس کو حاصل ہو چکی ہوں اور اُن نیکیوں کے حصول کی کوشش کرے جو اس کو ابھی ملی نہیں.غرض استقلال کے ساتھ بدیوں کا مقابلہ کرنے، استقلال کے ساتھ نیکیوں پر قائم رہنے اور استقلال کے ساتھ آئندہ نیکیوں کے حصول کے لئے کوششں کرنے کانام صبر ہے.دوسرے معنے صبر کے یہ ہیں کہ انسان جزع فزع نہ کرے.جب کوئی مصیبت آپڑے تو گھبرائے نہیں اور ہمت نہ ہارے.اگر اس کا کوئی عزیز مرتا ہے یا اس کا مال کھویا جاتا ہے.یا اسی قسم کا کوئی اور واقعہ پیش آتا ہے تو وہ اس امر کو مدنظر رکھے کہ جو کچھ اُس کے پاس ہے وہ اُس کا نہیں بلکہ بطور انعام خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہے اور صبر سے کام لے.پھر اس صبر کی بھی آگے دو قسمیں ہیں.ایک اُن معاملات میں صبر کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور بندوں کا ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا.اور دوسرے اُن معاملات میں صبر کرنا جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں.جو معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اُن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا یا بیمار ہو گیا.یا ملک میں قحط پڑ گیا یا کوئی ایسی جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے اُس کے کاروبار میں گھاٹا پڑ گیا.یہ ایسے واقعات ہیں کہ اِن میں انسان کا کوئی دخل نہیں.اِن میں خدا تعالیٰ کی رضا پر استقلال کے ساتھ قائم رہنا صبر کہلاتا ہے.لیکن ایسے معاملات جو بندوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اُن میں بعض دفعہ انسان ہاتھ پائوں ہلا سکتا ہے.لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس پر سختی کرتا اور اس کو دکھ دیتا ہے تو وہ مقابلہ نہیں کرتا مثلاً کوئی اُس کو تھپڑ مارتا ہے تو وہ آگے سے بولتا نہیں.خدا تعالیٰ تو اگر اُس کی جان بھی لے لے تو وہ بول نہیں سکتا.لیکن اگر کوئی شخص اُسے تھپڑمارے تو یہ بھی مناسب جواب دے سکتا ہے.اگر اس کو تھپڑ مارنا ہی مناسب ہو.تو تھپڑ مار سکتا ہے اور اگر اس وقت تھپڑ مارنا قومی فوائد کے لحاظ سے یا اس شخص کی اصلاح کے نقطہ نگاہ سے مناسب نہ ہو تو تھپڑ نہیں مارتا.بہرحال ایسی حالت میں اگر کوئی شخص خاموش رہتا ہے تو یہ صبر کہلاتا ہے لیکن اس حالت میں ضروری ہے کہ یہ شخص بُزدل نہ ہو اور اس وجہ سے چپ نہ ہو کہ دوسرا شخص بھی مجھے آگے سے مارے گا.خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں تو اس کا چُپ رہنا اور صبر کرنا عدمِ مقدرت پر مبنی ہو گا.لیکن انسانوں کے مقابلہ میں اس کا صبر عندالمقدرت ہو گا.یعنی اگر وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس لئے بدلہ نہیں لیتا کہ شاید بدلہ نہ لینے سے کوئی مفید نتیجہ نکل آئے تو یہ اس کا صبر کہلائے گا.مگر خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں یہ بدلہ لینے کی مقدرت ہی نہیں رکھتا وہاں اُس کا چُپ رہنا یا نہ رہنا برابر ہوگا.اس لئے وہاں صبر کے یہی معنے ہوں گے کہ گھبرائے نہیں اور ہمت ہار کر بیٹھ نہ رہے لیکن بندوں کے مقابلہ میں اس کو بدلہ لینے کی مقدرت ہو
Page 392
اور پھر صبر کرے تو صبر صبر کہلانے کا مستحق ہو گا کیونکہ یہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے صبر کرتا ہے اگر کوئی شخص قید میں کوٹھڑی کے اندر بند ہو.کوئی راستہ اُس کے نکلنے کا نہ ہو.اور وہ کہے کہ میں صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں تو یہ اس کا صبر نہیں ہو گا.کیونکہ اگر دروازہ کھلا ہوتا اور کوئی اُس کو نہ روکتا تو وہ ضرور قید سے نکل جاتا.اس کا اس وقت قید میں چپ بیٹھے رہنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اُس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا.پس اُس کا یہ صبر صبر نہیں کہلائے گا.غرض انسانوں کے مقابلہ میں صبر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو عندالمقدرت ہو.بے شک بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے.اس میں بدلہ لینے کی طاقت اور ہمت ہی نہیں ہوتی.اور وہ خیال کرتا ہے کہ اچھا میں صبر کرتا ہوں.مگر اُسے ہم صبر نہیں کہہ سکتے.صبر یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں بدلہ لے سکتاہوں لیکن پھر بھی وہ عفو سے کام لے.وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ اور وہ (یعنی یہودی اور مسیحی یہ بھی) کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے ان (لوگوں )کے جو یہودی ہوں یا نَصٰرٰى١ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ١ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ مسیحی ہوں ہرگز کوئی داخل نہ ہو گا یہ (محض )ان کی آرزوئیں ہیں.تو (انہیں ) کہہ دے کہ اگر تم كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۰۰۱۱۲ سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو.تفسیر.یہ مضمون مختلف شکلوں میں قرآن کریم میں تین دفعہ آیا ہے.پہلی دفعہ سورۂ بقرہ آیت۸۱ میں یہ مضمون اِس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں چنددن سے زیادہ نہیں چھوئے گی.گویا اہل کتاب دوزخ میں جائیں تو سہی.مگر اللہ تعالیٰ ان سے رعایت کا معاملہ کرے گا اور چند دنوں کے بعد جو اُن کی کتابوں میں زیادہ سے زیادہ بارہ ماہ تک شمار کئے گئے ہیں اُن کو دوزخ میں سے نکال لیا جائے گا.بلکہ بارھواں مہینہ بھی ختم نہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو آگ سے نکال لے گا.دوسری دفعہ یہ مضمون سورۃ بقرہ آیت۹۵ میں اِس طرح آیا ہے کہ قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ
Page 393
للّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.یعنی اہل کتاب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے صرف وہی مستحق ہیں اور جنت میں داخل ہونے کے وہی حقدار ہیں.اور کوئی قوم جنت میں داخل نہیں ہو گی.اس سے ظاہر ہے کہ بعض یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ انہیں عذاب ملے گا ہی نہیں بلکہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے اور کسی غیریہودی کو جنت نہیں ملے گی.اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو فرماتا ہے کہ اِن سے پوچھو اور دریافت کرو کہ اگر یہ صحیح ہے کہ جنت کے صرف تم ہی مستحق ہو اور کوئی قوم اس میں داخل نہیں ہو گی تو تم رضائے الٰہی کے لئے وہ کوشش کیوں نہیں کرتے جو موت کے مترادف ہوتی ہے.یا اس بات کے لئے مباہلہ کیوں نہیں کرتے.دوسروں کو تو تم اس سے محروم قرار دیتے ہو اور جنت صرف اپنے لئے مخصوص کرتے ہو.لیکن اگر یہ درست ہے تو تمہارے لئے تو خدا کے لئے اپنی زندگی وقف کرنا اور اس کی رضا کے حصول کے لئے کوشش کرنا اوّلین فرض ہو جاتا ہے.پھر تم کیوں ایسا نہیں کرتے.تیسری جگہ جہاں یہ مضمون بیان ہوا ہے یہ آیت ہے.اصل میں یہ دو الگ الگ فقرے ہیں جن کو عربی زبان کے محاورہ کے مطابق مختصر کر دیا گیا ہے اصل عبارت یوں ہے کہ وَقَالَتِ الْیَھُوْدُ لَنْ یَّدْ خُلَ الْجَنَّۃَ اِلَّا مَنْ کَانَ ھُوْدًا وَقَالَتِ النَّصَارٰی لَنْ یَّدْخُلَ الْجَنَّۃَ اِلَّا مَنْ کَانَ نَصَاریٰ یہود کہتے ہیں کہ جنت میں صرف یہود ہی داخل ہونگے اور کوئی داخل نہیں کیا جائے گا.اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف نصاریٰ ہی داخل ہونگے اور کوئی داخل نہیں ہو گا.پس یہ ایک فقرہ نہیں.کیونکہ کوئی یہودی یہ نہیں کہتا کہ جنت میں صرف یہود اور نصاریٰ ہی داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ میں سے کوئی کہتا ہے کہ صرف یہود اور نصاریٰ ہی جنت میں داخل ہوں گے.پس یہ الگ الگ فقرے ہیں.جن کو یکجا کر دیا گیا ہے.یہ تیسرا دعویٰ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے.کہ غیروں کو تو اہل کتاب جنت سے محروم کرتے ہی تھے ان کا آپس میں بھی اس قدر اختلاف ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق کو جنت سے محروم قرار دیتا ہے.گویا ایک جماعت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہودی دوزخ میں جا تو سکتے ہیں مگر وہ جلدی ہی نکال لئے جائیں گے.چنانچہ سیل نے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہود کے نزدیک یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ کوئی یہودی خواہ کیسا ہی گنہگار ہو گیارہ یا بارہ ماہ سے زیادہ دوزخ میں نہیں رہے گا.سوائے دو یہودیوں داتھن اور ایبی رام کے یا سوائے دہریوں کے جو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے.اسی طرح جیوش انسائیکلو پیڈیا میں بھی طالمود کے حوالہ جات سے یہود کے اس عقیدہ کو ثابت کیا گیا ہے(جیوش انسا ئیکلو پیڈیا زیر لفظ Gehenna) لیکن دوسری جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہود کو عذاب ملے گا
Page 394
ہی نہیں.اور ایک جماعت وہ ہے جو نجات کو اور بھی تنگ کر دیتی ہے اور یہودی صرف یہود کو اور عیسائی صرف عیسائیوں کو ہی نجات کا مستحق قرار دیتے ہیں اَور کسی کو نہیں.چنانچہ عیسائیوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ دوزخ دو ۲ قسم کی ہے.ایک مستقل اور دوسری عارضی.وہ کہتے ہیں کہ اگر عیسائی دوزخ میں جائیں گے تو وہ عارضی دوزخ میں جائیں گے.پھر وہاں سے نکال لئے جائیں گے.انہیں مستقل دوزخ میں داخل نہیں کیا جائے گا.اور بعض کہتے ہیں کہ جس کے دل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی ذرہ بھر بھی محبت ہو گی.وہ کسی حالت میں بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا.اس عقیدہ کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں.اور غلطی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یہود نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گو عیسائی بھی توریت اور بائیبل پر ایمان لاتے ہیں مگر وہ جنت میں داخل نہیں ہو ںگے.اور عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ گو یہود بائیبل پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ جنت میں داخل نہیں ہونگے.بلکہ صرف عیسائی ہی اس میں داخل ہوںگے.ترتیب مضامین کے لحاظ سے ان تین آیتوں میں سے پہلی آیت سورہ بقرہ کے نویں رکوع میں آتی ہے.اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہودی آپؐ کی مخالفت کرتے ہیں.مگر اُن کی یہ مخالفت ایمانداری کے طریق سے نہیں.یوں مخالفت ناجائز نہیں ہوتی کیونکہ اگر کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ مخالفت کرنے کا حق رکھتا ہے اور اگروہ کوئی بات غلط سمجھ کر مخالفت کر تا ہے تو وہ معذور ہوتا ہے.لیکن اگر کوئی شخص کسی مجلس میں بات سُن کر اور سمجھ کر جاتاہے اور پھر باہر جا کر اُس کی مخالفت شروع کر دیتا ہے تو اُس کی مخالفت دیانتداری پر مبنی نہیں ہوتی.پس مخالفت جائز ہے بشرطیکہ وہ دیانتداری سے ہو.اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر قسم کی علمی ترقی رُک جاتی.کیونکہ تمام علمی ترقیات اختلاف سے وابستہ ہوتی ہیں.پس مخالفت جائز ہے مگر وہ دیانت داری پر مبنی ہونی چاہیے اور اظہار اختلاف کا طریق شریفانہ ہونا چاہیے کسی قسم کی ضِد اور ہٹ نہیں ہونی چاہیے.مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ضِد اور ہٹ سے کام لیتے ہیں اور جان بوجھ کر قرآن کریم کی باتیں غلط رنگ میں بیان کرتے ہیں.پس اِن کی باتیں ایمانداری پر مبنی نہیں.ان کی مخالفت اُسی صورت میں دیانت داری پر مبنی ہو سکتی ہے جبکہ یہ حقیقۃً ان کو غلط سمجھتے ہوں اور اُن کے غلط ہونے کی دلیل بھی دیتے ہوں.لیکن اگر یہ لوگوں کے سامنے حقیقت پر پردہ ڈال کر اُسے غلط طریق سے پیش کرتے ہیں یا اس کے مقابلہ میں کوئی دلیل نہیں دے سکتے تو پھر یہ محض اُن کی شرارت ہے اور یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ اُن کو یہ یقین ہے کہ ہم آگ میں داخل نہیں ہو ںگے.اور جب کوئی قوم نجات کو ورثہ کے ساتھ وابستہ کرتی ہے تو اس قوم میں سے تقویٰ مٹ جاتا ہے.دنیا میں بالعموم دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں.بعض احسان اور محبت سے
Page 395
مانتے ہیں اور بعض ڈر اور خوف سے مانتے ہیں.عذاب کا ڈر ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو انہیں ناشائستہ حرکات سے روکتا ہے.لیکن اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے احسان اور محبت ہوتی ہے جو ان کو اس قسم کی حرکات سے باز رکھتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسے ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں کہ یہ صرف عذاب سے ہی ڈر سکتے تھے.مگر ان کی قوم نے ان سے کہا کہ تم عذاب سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیئے گئے ہو.اس لئے ان کے دلوں سے عذاب کا خوف نکل گیا.جس کی وجہ سے یہ حیاسوز حرکات کرتے ہیں.اگر انسان کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو تو پھر بھی وہ مادر پدر آزاد ہو سکتاہے مگر یہ باوجود مذہبی آدمی ہونے کے ایسی حرکات کرتے ہیں جو مادر پدر آزاد بھی نہیں کرتے.دوسری آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ جو قومیں انعامات الہٰیہ کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیتی ہیں وہ ہدایت کی جستجو بھی ترک کر دیتی ہیں.ہدایت کی جستجو کوئی قوم تبھی کرتی ہے جب وہ یہ یقین رکھتی ہو کہ ہدایت اور انعامات کا دروازہ کھلا ہے.لیکن جو قوم یہ یقین رکھتی ہو کہ ہدایت صرف ہماری ہی قوم کے ساتھ مخصوص ہے وہ تو صرف انہی باتوں کو جو اُن کی کتابوں میں لکھی ہوںدرست سمجھے گی اور دوسری طرف نظر اُٹھا کر بھی نہیں دیکھے گی.اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم نجات کو صرف اپنے تک محدود کر کے اُسے تنگ کر دیتی ہے اور اس میں ناواجب ضِد پیدا ہو جاتی ہے جو اُسے تقویٰ سے دُور لے جاتی ہے.زیر تفسیر آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اِس قسم کے عقائد کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قومیں دائرہ نجات کو محدود کرتی جاتی ہیں اور پھر آپس میں بھی ایک دوسرے کو نجات سے محروم کر دیتی ہیںاورتقویٰ جو اصل معیار ہے وہ اُن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے حالانکہ کسی وقت بھی کسی شخص کو ہدایت کا دروازہ بند نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ جو کلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو اس کو قبول کر لینے کے لئے تیار رہنا چاہیے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ لَنْ یَّدْخُلَ الْجَنَّۃَ اِلَّا مَنْ کَانَ ھُوْدًااَوْنَصَارٰی کا یہ مطلب نہیں کہ یہود کا یہ کہنا کہ صرف یہودی ہی نجات پائے گا کوئی بُری بات ہے.کیونکہ ہر مذہب والا اپنے آپ کو ہی نجات یافتہ کہتا ہے بلکہ ایک مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے.پس اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود اپنے مذہب میں نجات کو کیوں محدود قرار دیتے ہیں یاعیسائی عیسائیت میں نجات کیوں سمجھتے ہیں.بلکہ مراد یہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ نجات کو مخصوص قرار دے کر یہ لوگ خدا تعالیٰ کے وسیع فیضان کو محدود کرتے ہیں اور دنیا کے ایک بڑے حصہ کو اُس کی رحمت سے محروم قرار دیتے ہیں.ورنہ قرآن کریم کا یہ منشاء نہیں کہ اُن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہودیت کے بغیر نجات نہیں یا عیسائیت کے بغیر نجات نہیں.اسلام کا بھی تو یہی دعویٰ ہے کہ اس کے
Page 396
بغیر نجات نہیں مگر جہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی بنی نوع انسان کی نجات کا ذریعہ ہے.وہاں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کے دروازہ کو بند نہیں کرتا.بلکہ کہتا ہے کہ وَبِا لْاَخِرَۃِ ھُمْ یُوْقِنُوْنَ.یعنی مومنوں کی یہ علامت ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی تازہ کلام نازل ہو وہ فوراً اُس پر ایمان لے آتے ہیں.پس وہ نجات کو کلامِ الہٰی پر ایمان لانے کے ساتھ وابستہ قرار دیتا ہے.خواہ وہ کلام کسی پہلے زمانہ میں نازل ہو چکا ہو یا آئندہ نازل ہو.اس کے مقابلہ میں عیسائیوں اور یہودیوں میں سے یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بغیر نجات نہیں اور وہ اپنے مذہب میں کسی کو داخل بھی نہیں کرتے.کیونکہ وہ دوسروں میں سے کسی کی نجات کے قائل نہیں.وہ صرف اپنی قوم کے ساتھ نجات کو مخصوص کرتے ہیں نہ کہ اپنے مذہب کے ساتھ لیکن عیسائی اپنی قوم کے ساتھ نجات مخصوص نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مذہب کے ساتھ اُسے مخصوص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسروں میں سے ہر شخص عیسائیت میں داخل ہو کر نجات پا سکتا ہے گویا عیسائیت کو اسلام سے ایک ظاہری مشابہت یہ حاصل ہے کہ عیسائی بھی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور ہدایت کو کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں کرتے اور اسلام بھی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے اندر شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے اور ہدایت کو کسی خاص قوم سے مخصوص نہیں کرتا.اور چونکہ ان دونوں میں یہ ایک ظاہری مشابہت پائی جاتی ہے.اس لئے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اگر عیسائیوں کا یہ کہنا کہ صرف عیسائی مذہب میں نجات ہے قابل اعتراض ہے تو اسلام کا یہ کہنا کہ صرف اسلام میں نجات ہے کیوں قابلِ اعتراض نہیں؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام اور عیسائیت کے اِن دعووں میں جو ظاہری مشابہت پائی جاتی ہے وہ درحقیقت کوئی حقیقی مشابہت نہیں بلکہ ایک خود ساختہ مشابہت ہے.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گو عیسائی تمام دنیا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں مگر اُن کا مذہب اُن کو غیر مذاہب کے لوگوں کو اپنے اندر شامل کرنے کی اجازت نہیں دیتا.اس کا ثبوت ہمیں اناجیل سے واضح طور پر نظر آتا ہے.متی باب۷ آیت۶ میں لکھا ہے.’’وہ چیز جو پاک ہے کتوں کو مت دو.اور اپنے موتی سؤروں کے آگے نہ پھینکو ایسا نہ ہو کہ وے انہیں پامال کریں اور پھر کر تمہیں پھاڑیں.‘‘ اس حوالہ میں بتایا گیا ہے کہ مسیح ؑناصری کی معرفت جو تعلیم تم لوگوں کو ملی ہے وہ موتیوں کی طرح ہے.وہ صرف اسرائیلیوں کے لئے رہنی چاہیے.اسے غیر قوموں کے سامنے نہیں رکھناچاہیے.کیونکہ بقول انجیل غیر قومیں سؤروں اور کتوں کی طرح ہیں.اگر یہ تعلیم اُن کے سامنے گئی تو وہ اُسے توڑ کر ردّی کی طرح پھینک دیں گی.اور اس کے غلط
Page 397
معنے کرکے اس پر حملہ کریںگی اور اس کی ہتک کا ارتکاب کریں گی.(۲) متی باب۱۰ آیت۵،۶ میں لکھا ہے.’’ان بارھوں کو یسوع نے فرما کے بھیجا کہ غیر قوموں کے طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ پہلے بنی اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جائو.‘‘ اِس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح ؑ نے اپنے حواریوں کو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لئے ہی بھیجا تھا.اور انہیں واضح طور پر یہ ہدایت دی تھی کہ غیر اقوام کو تبلیغ نہ کریں.اس جگہ عیسائی ایک لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہیں.وہ کہتے ہیں کہ یہاں ’’پہلے‘‘ کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے.اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی زمانہ میں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ محدود ہو گی.مگر آئندہ زمانہ میں انہیں اپنی تبلیغ وسیع کرنے کی اجازت ہو گی.لیکن اسی باب کی آیت۲۳ اس مفہوم کو ردّ کر دیتی ہے.اُس میں لکھا ہے.’’میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے جب تک کہ ابن آدم نہ آئے.‘‘ اِس میں حضرت مسیح ؑ کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میری آمد ثانی تک تمہاری یہ تبلیغ غیروں میں شروع نہیں ہوگی اور جب تک کہ ابن آدم دوبارہ دنیا میں نہ آئے تمہارا یہ مشن جو بنی اسرائیل میں قائم کیا گیا ہے ختم نہیں ہو گا.ہاںجب وہ آجائے گا تو پھر اجازت ہو گی کہ دوسروں کو بھی تبلیغ کی جائے.پس’’پہلے ‘‘ کی تشریح اس باب کی آیت نمبر۲۳ نے کردی ہے.اسی طرح متی باب۱۵ آیت۲۴ میں لکھاہے:.’’اُس نے جواب میں کہا.میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی پاس نہیں بھیجا گیا.‘‘ یہاںحضرت مسیح ؑ اس بات کا صاف طور پر اقرار کرتے ہیں کہ میں اسرائیلیوں کے سوا کسی اور کی طرف نہیں بھیجا گیا.پس پہلے اور بعد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.اِسی طرح مرقس باب۷ آیت ۲۷ میں آتا ہے:.’’یسوع نے اُسے کہا کہ پہلے فرزندوں کو سیر ہونے دے.کیونکہ فرزندوں کی روٹی لے کے کتوں کے آگے ڈالنا لائق نہیں.‘‘
Page 398
یہاں بھی متی باب۱۰ والے حوالہ کا مضمون ہے اور اس میں بھی غیر اسرائیلیوں کو کتّےقرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ روٹی کتوّں کے لئے نہیں بلکہ صرف اسرائیلیوں کے لئے ہے.اس کے مقابلہ میں اسلام اپنی تبلیغ کو کسی خاص قوم تک محدود نہیں کرتا.چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے متعلق فرماتا ہے قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (الاعراف:۱۵۹) یعنی اے رسول! تو کسی ایک قوم کو نہیں بلکہ تمام دنیا کی قوموں کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں.دوسری جگہ سورۂ سبا میں فرماتا ہے وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (سبا :۲۹) یعنی ہم نے تجھے تمام بنی نوع انسان کی طرف ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے جو مومنوں کو خوشخبری دینے والا اور کافروں کو ہوشیار کرنے والا ہے لیکن انسانوں میں سے اکثر اس حقیقت سے آگاہ نہیں.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیںکَانَ کُلُّ نَبِیٍّ یُبْعَثُ اِلٰی قَوْمِہٖ خَآصَّۃً وَبُعِثْتُ اِلیٰ کُلِّ اَحْمَرَوَ اَسْوَدَ.(مسلم کتاب المساجد،باب المساجد و مواضع الصلوٰة)یعنی مجھ سے پہلے جس قدر انبیاء تھے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے مگر مجھے ہر اسود و احمر کی طرف مبعوث کیا گیا ہے.غرض قرآن کریم میں بھی یہ دعویٰ موجود ہے اور ر سول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے بھی بتا دیا ہے کہ آپ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے.ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اُرْسِلْتُ اِلَی الْخَلْقِ کَآفَّۃً (مسلم کتاب المساجد).مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے.پس گو بظاہر اسلام اور عیسائیت کے متبعین کا دعویٰ مشترک معلوم ہوتا ہے.مگر عیسائی ایسی بات کہتے ہیں جو اُن کے اپنے مذہب کے خلاف ہے.جب خدا تعالیٰ نے عیسائیت کو غیر مذاہب والوں کے لئے رکھا ہی نہیں تو وہ اُسے قبول کر کے نجات کس طرح حاصل کرسکتے ہیں؟ اگر ایک گورنمنٹ کسی کو کہیں جانے کا حکم دے اور وہاں کوئی اَور چلا جائے تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے.اِسی طرح اگر کوئی غیر اسرائیلی عیسائی ہو جائے گا تو وہ انعام کا نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہو گا.پھر ایک اور نقطۂ نگاہ سے بھی اسلام اور دوسرے مذاہب میں فرق ہے.اور وہ یہ کہ یہود و نصاریٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ لَنْ یَّدْ خُلَ الْجَنَّۃَ اِلَّا مَنْ کَانَ ھُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی کہ یہود اور نصاریٰ کے سوا اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو گا.یہاں کسی ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں بلکہ یہ ذکر ہے کہ سو، ہزار، لاکھ بلکہ کڑور سال کے بعد بھی یہود اور نصاریٰ کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہو گا.مگر اسلام کی تعلیم اس سے مختلف ہے.وہ دوزخ کے عذاب کو دائمی قرار نہیں دیتا.بلکہ کہتا ہے کہ کوئی انسان خواہ دہریہ بھی ہو آخر ایک دن جنت میں داخل ہوجائے گا.کیونکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ
Page 401
کا یہ سلوک نہیں تو اُن کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اُن سے اپنی برکات چھین لی ہیں اور انہیں مر کر بھی نجات حاصل نہیں ہوگی.بَلٰى ١ۗ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ (اور بتاؤ کہ دوسرے لوگ) کیوں نہیں (داخل ہوں گے)جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیک عِنْدَ رَبِّهٖ١۪ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَؒ۰۰۱۱۳ کام کرنے والا (بھی)ہو تواس کے رب کے ہاں اس کے لئے بدلہ (مقرر )ہے اور ان کو( یعنی ایسے لوگوں کو آئندہ کے متعلق )کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ (کسی سابق نقصان پر )غمگین ہوں گے.حَلّ لُغَات.اَسْلَمَ کے معنے ہیں اپنے آپ کو کسی کے سُپرد کر دینا یا کلّی طور پر سونپ دینا.(اقرب) وَجْہٌ کے کئی معنے ہیں(۱) توجہ (۲) نَفْسُ الشَّیْءِ کسی چیز کا وجود(۳) چہرہ.یہ سب معنے یہاں چسپاں ہو سکتے ہیں.اور اِس آیت کے معنے یہ ہیں کہ (۱)جو اپنی توجہ پورے طور پر خدا کو سونپ دے یعنی تمام تر توجہ خدا کی طرف لگا دے.(۲) جو اپنی ذات کو کامل طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اسے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے(۳)جو اپنا چہرہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے.ہروقت اس کی طرف نظر رکھے اور اُس کی نگاہ کبھی غیر اللہ کی طرف نہ اُٹھے.(اقرب) مُحْسِنٌ.احسان کے دو معنے ہیں(۱) دوسرے کو انعام دینا بغیر اُس کے کسی کام کے اُس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرنا یا اس کے کام کے بدلہ سے اُسے زیادہ دینا (۲) انسان کا اپنے ذاتی کام میں کمال کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا.یعنی اُسے اپنے کام کے متعلق اچھا علم حاصل ہو.یا جو عمل کرے وہ اچھا ہو.غرض احسان یہ ہے کہ (۱)غیر کے ساتھ بغیر بدلہ کے نیک سلوک کرے(۲) اپنے علم اور عمل میں نیکی مد نظر رکھے اور اُس میں بدی کو داخل نہ ہونے دے.(مفردات)حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے.اَلنَّاسُ اَبْنَا ءُ مَا یُحْسِنُوْنَ کہ لوگ اس چیز کے بیٹے ہوتے ہیں جسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں.یعنی انسان کی عزت اس علم کے مطابق ہوتی ہے جسے وہ اچھی طرح سیکھتا ہے اور اس عمل کے مطابق ہوتی ہے جسے وہ بہترسے بہتر کر سکتا ہے.جیسے ایک شخص نجّار کہلاتاہے وہ کئی اور کام بھی
Page 402
جانتا ہے.مثلاً وہ روٹی پکا سکتا ہے.زراعت کا علم رکھتا ہے اور اُسے کر سکتا ہے یا لوہار کا کام بھی جانتا ہے اور اس سے کام چلا سکتا ہے مگر وہ کہلاتا نجّارہے اس لئے کہ سب سے زیادہ اُسے نجّاری کا کام آتا ہے.اِسی طرح کاتب کئی اور کام بھی جانتااور کر سکتا ہے مگر کاتب کہلاتا ہے.اس لئے کہ وہ سب سے زیادہ کتابت جانتا ہے اور یہ اُس کا پیشہ ہے.اِسی طرح ڈاکٹر باوجود کئی اور کام جاننے کے صرف ڈاکٹر کہلاتا ہے.اس لئے کہ وہ ڈاکٹری کا کام سب سے زیادہ جانتا ہے.پس محسن وہ ہے جو کامل علم رکھنے والا یا کامل عمل کرنے والا ہو.اِسی طرح اَحْسَنَ الشَّیْ ءَ کے معنے ہیں جَعَلَہٗ حَسَنَۃً اُسے اچھا بنایا.جیسے قرآن کریم میں آتا ہے الَّذِیْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ (السَّجدة :۸)کہ جس نے ہر چیز پیدا کی اور کام کے لحاظ سے اُسے بہتر سے بہتر طاقتیں بخشیں.احسان، انعام سے مختلف چیز ہے.انعام صرف دوسرے پر ہوتا ہے اور احسان اپنے نفس پر بھی ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی پس تمام بنی نوع انسان سے نیک سلوک کرنا احسان ہے.عدل کے لحاظ سے بھی احسان مقام بلند ہے.عدل تو یہ ہے کہ جتنا کسی کا حق ہو اُتنا ہی انسان اُسے دے دے اِس سے زیادہ نہ دے مگر احسان یہ ہے کہ جو کسی کا حق ہو اس کو اصل سے زیادہ ادا کیا جائے.اور جو لینا ہو وہ حق سے کم لیا جائے.(مفردات راغب) اقرب میں اس سے زیادہ مختصر معنے یہ لکھے ہیں کہ اَتٰی بِالْحَسَنِ.اچھی بات کہی یا اچھی بات جانی.یا اچھا کام کیا.یہ اَسَاءَ کی ضد ہے.یعنی بدسلوکی کے مخالف معنے دیتا ہے.پس اس کے معنے بھی حسنِ سلوک ہی کے ہیں.اَحْسَنَہٗ کے معنے عَلِمَہٗ کے بھی ہیں یعنی اُسے اچھی طرح سے جان لیا.کہتے ہیں فُـلَانٌ یُحْسِنُ الْقِرَاءَ ۃَ فلاں شخص قراء ت کا خوب علم رکھتا ہے اور اَحْسَنَ لَہٗ وَبِہٖ کے معنے ہیں اچھا عمل کیا یا کسی کے ساتھ نیکی کی.(اقرب) اسلامی نقطۂ نگاہ سے اَسْلَمَ وَجْھَہٗ اور وَھُوَ مُحْسِنٌ کے یہ معنے ہیں کہ ایسا شخص رسول کی اتباع کرتا ہو.اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرمانبرداری کرے.حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖ وسلم نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَیْسَ عَلَیْہِ اَمْرُنَا فَھُوَ رَدٌّ(بخاری کتاب البیوع باب النجش....)کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کے متعلق ہمارا حکم نہیںیا جس میں ہماری اجازت نہیں وہ مقبول نہیں ہو گا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖ وسلم جو کلامِ الہٰی کے لانے والے ہیں وہی خدا تعالیٰ کے منشا کو بہتر سمجھ سکتے ہیں.حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا
Page 403
کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا.اَنْ تَعْبُدَ اللّٰہَ کَاَ نَّکَ تَرَاہُ فَاِنْ لَّمْ تَکُنْ تَرَاہُ فَاِنَّہٗ یَرَاکَ (بخاری کتاب الایمان باب سوال الجبریل النبی عن الایمان....) کہ ُتو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی طرز پر کرے کہ وہ تجھے نظر آجائے یا کم از کم تجھے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے.درحقیقت یہ ایک معیار ہے انسان کی روحانی ترقی پہچاننے کے لئے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے بتایا ہے کہ عبادتِ الہٰی اتنی کامل ہو جائے کہ خدا تعالیٰ نظر آنے لگے.یا اُس پر اتنی ہیبت طاری ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں.خدا کو نظر کے سامنے رکھنے سے انسان کا دل بڑھ جاتا ہے جس طرح بھاگتی فوج بادشاہ کے آنے سے کھڑی ہو جاتی ہے.لیکن اگر اِن دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ محسن نہیں رہتا.حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی رُو سے مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ کے یہ معنے ہیں(۱) کہ جو اپنی توجہ کو خدا کے سپرد کر دے اور وہ پورے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖ وسلم کا بھی مطیع ہو.دوسری روایت کی رُو سے یہ معنے ہیں(۲) کہ جو اپنی توجہ کو پورے طور پر خدا تعالیٰ کے سپرد کردے اور رُوحانی طور پر اتنا کامل ہو جائے کہ اُسے خدا تعالیٰ نظر آنے لگ جائے یا خدا کے حکم کے مطابق اس کا عمل ہو جائے.گویا ایک طرف خدا تعالیٰ کے منشا کے مطابق اس کا عمل ہو اور دوسری طرف اس کا علم کامل ہو اور اس کا عمل عرفان کے درجہ تک پہنچ جائے.لُغت کی رو سے اس کے یہ معنے ہیں کہ جو شخص اپنی نظر خدا تعالیٰ کی طرف رکھے.کسی انسان سے اُس کی اُمید وابستہ نہ ہو.اس کی امید گاہ وہی ہو.اور دوسری طرف و ہ محسن بھی ہو یعنی اس کا عمل اتنا وسیع ہو کہ کوئی شخص اُس کے حسنِ سلوک سے باہر نہ رہے گویا اُس کا احسان ساری دنیا سے وابستہ ہو.تفسیر.یہ آیت وَقَالُوْالَنْ یَّدْ خُلَ الْجَنَّۃَ اِلَّا مَنْ کَانَ ھُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی کے جواب میں نازل کی گئی ہے.اور بتایا گیا ہے کہ اسلام کے معنے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق درست رکھنا اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنا.پس نجات کا مستحق صرف وہی شخص ہے جو ایک طرف تو اپنے آپ کو کلیۃً اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر ڈال دے اور جو کچھ مانگنا ہو اُس سے مانگے.اور دوسری طرف اُس کا دامن اتنا وسیع ہو کہ آپ دوسروں سے لینے کے لئے تیار نہ ہو بلکہ ہر ایک کو دینے کے لئے آمادہ رہے.اسی مضمون کا ایک شعر میںنے بھی کہا ہے کہ ؎ تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو یہ محسن کا کمال ہے کہ وہ اپنے لئے خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے اور پھر سب دنیا کو دیتا ہے.اور درحقیقت انابت الی اللہ.توجہ الی اللہ اور شفقت علی الناس ہی اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہے.بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ
Page 404
حضرت مرزا صاحب ؑ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ دو۲ باتیں اسلام کا خلاصہ ہیں اس کا ثبوت کیا ہے؟ سو وہ خلاصہ اسی آیت میں درج ہے مَنْ اَسْلَمَ میں انابت الی اللہ آجاتی ہے اور وَھُوَ مُحْسِنٌ میں لوگوں پر شفقت آجاتی ہے اور بَلٰی کہہ کر بتا دیا کہ نجات صرف انہی لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ تمہارے ساتھ.ایسے لوگوں کے لئے اُن کے ربّ کے پاس اُن کا اجر محفوظ رہے گا.اِس میں ایک لطیف بات بیان کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نجات ہمارے ساتھ مخصوص ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نجات کا گُر تو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے نہ کہ کوئی خاص مذہب اختیار کرنا پس محض نام نجات نہیں دلاسکتا بلکہ جب بھی خدا تعالیٰ کا کوئی نیا حکم آئے تو اُسے قبول کرنا ہی حقیقی اسلام ہے اور اُس کا انکار کرنا نجات کے مخالف.باقی رہا یہ کہ اِن کے علاوہ کوئی ناجی ہے یا نہیں؟ سو اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام قانون کے طور پر صرف اُنہی لوگوں کو نجات کا مستحق بتاتا ہے جو اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ کے ماتحت آتے ہوں.باقی خدا تعالیٰ مالک ہے جسے چاہے بخش دے.اگر وہ کسی ہندو کو بخشنا چاہے یا کسی سکھ کو بخشنا چاہے یا کسی عیسائی اور یہودی کو بخشنا چاہے تو اُسے کون روک سکتا ہے.بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر سچے مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سارے وجود کو خدا تعالیٰ کے لئے وقف کر دے.اور اپنی دنیوی حاجات کو بھی دینی حاجات کے تابع کر دے.بظاہر یہ ایک معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اسلام اور دیگر ادیان میں یہی فرق ہے.اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم علم حاصل نہ کرو.نہ یہ کہتا ہے کہ تم تجارتیں نہ کرو.نہ یہ کہتا ہے کہ صنعت و حرفت نہ کرو.نہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنی حکومت کی مضبوطی کی کوشش نہ کرو.وہ صرف انسان کے نقطۂ نگاہ کو بدلتا ہے.دنیا میںتمام کاموں کے دو نقطۂ نگاہ ہوتے ہیں.ایک قشر سے مغز حاصل کرنے کا نقطۂ نگاہ ہوتا ہے اور ایک مغز سے قشر حاصل کرنے کا نقطۂ نگاہ ہوتا ہے جو شخص قشر سے مغز حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے بلکہ اکثر وہ ناکام رہتا ہے.لیکن جو شخص مغز حاصل کرتا ہے.اس کو ساتھ ہی قشر بھی مل جاتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور آپ کے اتباع کی تمام جدو جہد دین کے لئے تھی لیکن یہ نہیں کہ وہ دنیوی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہوں.جن لوگوں کو دین ملے گا دنیا لونڈی کی طرح اُن کے پیچھے دوڑتی آئے گی لیکن دنیا کے ساتھ دین کا ملنا ضروری نہیں.بسا اوقات وہ نہیں ملتا اور بسا اوقات رہا سہا دین بھی ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے.لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.خوف آئندہ آنے والی باتوں کے لئے ہوتا ہے اور حُزن ماضی پر.اللہ تعالیٰ
Page 405
فرماتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہے.ان کو کوئی قوم نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اُن کی ماضی بھی اُن کو کبھی پریشان نہیں کر سکتی.اگر اللہ تعالیٰ ماضی معاف نہ کرتا تو انہیں فکر ہی لگی رہتی کہ ہم نے تیس، چالیس، پچاس، ساٹھ یا سو سال کی عمر ضائع کر دی اور نافرمانیاں کرتے رہے.مگر اِدھر وہ اَسْلَمَ وَجْھَہٗ پر عمل کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اُدھر اس کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں.گویا مومن کی ماضی اُسے کبھی پریشان نہیں کر سکتی.کیونکہ وہ ایمان لانے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ.اگر بعد میں وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا تو بے شک وہ اس کے نامۂ اعمال میں لکھا جائیگا.مگر توبہ کے بعد پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں.غرض اس آیت میں بتایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے اور مخلوقِ خدا پر بھی اس کے احسان کا دائرہ وسیع ہو اُسے نہ کوئی خوف ہو گا اور نہ حُزن.کیونکہ ایسا شخص خدا تعالیٰ کی پناہ میں آجاتا ہے.خوف اس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے.جو یا تو آخرت پر قطعی طور پر ایمان نہیں رکھتااور سمجھتا ہے کہ جب مر گئے تو خاک ہو جائیں گے اس لئے وہ موت سے ڈرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے عیش کے دنوں کو لمبا کرے اور یا پھر خوف اس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو مرنے کے بعد آنیوالی زندگی پر ایمان تو رکھتا ہے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا.وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو خدا کو کیا جواب دوں گا.لیکن وہ جو آخرت پر سچا ایمان رکھتا ہے اور اُس ایمان کے مطابق اعمال بھی بجا لاتا ہے اُس کے دل میں کوئی خوف نہیں رہتا.دوسری چیز حُزن ہے.خوف آئندہ کے متعلق ہوتا ہے لیکن حُزن ماضی کے متعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سچے مومن ہوں اُن کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ انہیں حُزن بھی نہیں ہوتا.ایک صدمہ ایسا ہوتا ہے جو اِتّصال اور محبت کی وجہ سے کسی چیز کے ضائع ہونے پر ہوتا ہے.اس صدمہ کو محسوس کرنے اور اس کے اظہار سے خدا نے منع نہیں فرمایا.لیکن حُزن یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی گزشتہ کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی کوئی تائید نہیں کرے گا.فرماتا ہے جسے خدا پر کامل ایمان ہو حُزن اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا.کیونکہ وہ اپنے خدا کی محبت اور اُس کی قدرتوں پر کامل یقین رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ خدا اپنے مخلص بندوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا.ترتیب و ربط: گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس منصوبہ کا ذکر کر کے جو وہ غیر سلطنتوں سے کرتے تھے آیت۱۰۵و۱۰۶ میں اُن کے دوسرے منصوبہ کا ذکر کیا جو وہ خود مسلمانوں میں بدامنی پیدا کرنے کے لئے کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمان گستاخی میں مبتلا ہو کر انعاماتِ الٰہیہ سے محروم ہو جائیں آیت۱۰۷ میں بتایا کہ ہم کسی کلام کو منسوخ کرتے ہیں تو اُس سے بہتر لاتے ہیں.پس یہود سوچیں کہ کیا موسیٰ ؑ اور دیگر انبیاء پر جو
Page 406
کلام نازل ہوتا تھا اس کے اثر اور اشاعت کو کوئی قوم روک سکی تھی جواب یہ روک لیں گے.آیت۱۰۸ میں بتایا کہ یہ کلام زمین و آسمان کے بادشاہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی مخالفت کا نتیجہ خطرناک ہوگا.آیت۱۰۹و۱۱۰ میں یہود کی تیسری تدبیر کا ذکر ہے جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے خلاف کیا کرتے تھے.اور وہ یہ کہ نہایت لغو اور بیہودہ سوالات کرتے تاکہ مسلمان بھی اُن کی دیکھادیکھی اِس مرض میں مبتلا ہو جائیں اور آہستہ آہستہ دین الہٰی کی عظمت اُن کے دلوں سے مٹ جائے.خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے کہ دیکھو یہ لوگ حضرت موسیٰ ؑ سے ایسے سوالات کر کے ہلاک ہو چکے ہیں اور اب تمہیں غافل اور گستاخ اور کافر بنانا چاہتے ہیں.آیت۱۱۱ میں اُن کے شر سے بچنے کی تدبیر بتائی کہ عبادت میں لگ جائو اور مخلوق کی ہمدردی کرو.آیت ۱۱۲ میںمسیحیوں کا بھی ذکر کر دیا(جو موسوی مذہب کی ایک شاخ تھے مگر یہودیوں سے بالکل الگ ہو چکے تھے) اور فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ نے ایک نیا عہد باندھا ہے اور اُن کی کتابوں میں اس کی خبر ہے تو اب اس سے منہ موڑ کر صرف یہودی یا عیسائی کہلانے سے کیونکر نجات ہو سکتی ہے.آیت۱۱۳ میں اُن کے خیالات کو ردّ فرما کر نجات کا حقیقی ذریعہ بتایا جو خدا تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری اور اس کی مخلوق پر شفقت سے کام لینا ہے.وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ١۪ وَّ قَالَتِ اور یہودی کہتے ہیں کہ مسیحی کسی (سچی) بات پر قائم نہیں ہیں.اور مسیحی کہتے ہیں النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ١ۙ وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ١ؕ کہ یہود کسی (سچی) بات پر قائم نہیںہیں.حالانکہ وہ دونوں (ایک ہی ) کتاب(یعنی تورات) پڑھتے ہیں.كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ١ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ اسی طرح وہ (دوسرے) لوگ جو علم نہیںرکھتے انہی کی سی بات کہا کرتے تھے.بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ۰۰۱۱۴ سو جس (بات) میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا.تفسیر.فرمایا یہ لوگ تمہیں تو غیر ناجی قرار دیتے ہیں لیکن خود ان کی یہ حالت ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ
Page 407
نصاریٰ میں کوئی خوبی نہیں پائی جاتی اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہوداپنے اندر کوئی نیکی اور روحانیت نہیں رکھتے.حالانکہ دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں.یہ بھی کہتے ہیں کہ بائیبل پر ہمارا ایمان ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بائیبل پر ہمارا ایمان ہے.صرف انجیل کے متعلق ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے.یعنی یہود تو اسے کوئی مقدس کتاب تسلیم نہیں کرتے اور عیسائی اس پر ایمان رکھتے ہیں.لیکن بائیبل جس میں تمام عہد نامہ قدیم شامل ہے اس پر یہود اور عیسائی دونوں ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں کہ اس میں کئی خوبیاں پائی جاتی ہیں.مگر ایک کتاب پر ایمان رکھنے کے باوجود ان میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہودی عیسائیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خوبی نہیں اور عیسائی یہودیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان میں کوئی خوبی نہیں.اِس سے پہلے یہود کے تین دعووںکا ذکر آچکا ہے.اب ان کے متعلق یہ چوتھی بات بیان کی گئی ہے درحقیقت پہلی دو باتیں آپس میں مشابہ تھیں اور آخری دو باتیں آپس میں مشابہ ہیں.پہلے کہا تھا کہ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَیَّامًا مَّعْدُوْدَۃً ہمیں آگ صرف چند دن چھو ئے گی اور گیارھویں رکوع میں اُن کا یہ دعویٰ بیان کیا گیا تھا کہ اگلا جہان صرف ہمارے لئے مخصوص ہے.گویا پہلے دعویٰ سے دوسرا دعویٰ بڑھ گیا.پہلا دعویٰ یہ تھا کہ اگرہم دوزخ میں جائیں گے تو صرف چند دن ہی اُس میں رہیں گے.اور دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں ہمارے سوا اور کوئی جا ہی نہیں سکتا.یہ پہلے دعویٰ سے بڑھ کر دعویٰ ہے.اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعووں کا ردّ کر دیا.اب تیسرا اور چوتھا دعویٰ آپس میں مشابہ ہیں.مگر چوتھا تیسرے سے بڑھ کر ہے.تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ لَنْ یَّدْ خُلَ الْجَنَّۃَ اِلَّا مَنْ کَانَ ھُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی کہ یہود کے نزدیک یہودیوں کے سوا اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور عیسائیوں کے نزدیک عیسائیوں کے سوا کوئی اور جنت میں داخل نہیں ہو گا.اور چوتھا دعویٰ یہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے کہ دوسروں کے جنت میں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوسکتا.یہود کے نزدیک عیسائیوں میں کوئی نیکی نہیں اور عیسائیوں کے نزدیک یہود میں کوئی خوبی نہیں.یوں دوزخ میں جانے والوں میں بھی بعض نیکیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ آخر ایک یا دو نیکیوں سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا.جنت میں انسان اسی صورت میں داخل ہوتا ہے جب نیکیاں زیادہ ہوں اور بدیاں کم ہوں.مگر یہ لوگ ایک دوسرے کو دوزخی قرار دینے میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے سوا دوسروں میں کوئی نیکی پائی ہی نہیں جاتی.گویا قطعی طور پر وہ کسی نیکی کو دوسرے کی طرف منسوب کرنے کے لئے تیارہی نہیں ہوتے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باقی نیکیوں کو تم جانے دو.تم یہ بتائو کہ عہدِ عتیق کا پڑھنا نیکی ہے یا نہیں ؟ وہ کم از کم اسے تو پڑھتے ہیں اور جب وہ یہ نیکی کا کام کرتے ہیں تو پھر کلّی طور پر کسی کی نیکی کا کیوں انکار کرتے ہو.
Page 408
حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب اپنے اندر بعض صداقتیں رکھتا ہے اور سچے مذہب کے صرف یہی معنے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نسبت اپنے اندر بہت زیادہ خوبیاں اور کمالات رکھتا ہے اور ہر قسم کے نقائص سے منزہ اور پاک ہوتا ہے.ورنہ تھوڑی بہت صداقت تو ہر مذہب میں پائی جاتی ہے.لیکن افسوس ہے کہ عام طور پر اس اصل کو نہیں سمجھا جاتا.جس کا نتیجہ شدید مذہبی عداوت کی شکل میں رونما ہوتا ہے.اسلام اس کم حوصلگی بلکہ غلط بیانی کا شدید مخالف ہے.اور اپنی صداقت کے دعویٰ کے ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کرتاہے کہ ہر مذہب اپنے اندر بعض خوبیاں رکھتا ہے اور مختلف مذاہب کے پیرؤوں کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر اندھا دھند حملہ نہ کیا کریں.بلکہ دوسروں کی خوبیوں کو بھی دیکھا کریں.اور بلا غور وتحقیق مذہبی تعصب کی بنا پر یہ خیال نہ کر لیا کریں کہ دوسرا مذہب سر سے پاتک عیوب کا مجسمہ ہے اور ہر قسم کی خوبی اس میں مفقود ہے.چنانچہ آیت مذکورہ بالا میں یہودیوں اور مسیحیوں کو ملامت کی گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس قدر سخت عداوت رکھتے ہیں کہ دوسروں کی کسی خوبی کے قائل ہی نہیں بلکہ تعصب مذہبی سے اندھے ہو کر فریق مخالف کو سراسر غلطی پر خیال کرتے ہیں.حالانکہ اگر اور کچھ نہ ہو تو کم از کم دونوں ایک ہی کتاب کے پڑھنے والے ہیں.پس اس ایک خوبی میں تو دونوںمشترک ہیں.اگر قرآن کریم کی اس تعلیم پر لوگ عمل کریں تو دُنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے.اور ہر قسم کے جھگڑے اور مناقشات دُور ہو کر صحیح معنوں میں امن قائم ہو سکتا ہے.کیونکہ تمام مذہبی جھگڑوں کی بنیاد اِسی غلط فہمی پر ہے.لوگ مخالف مذہب پر غور کرنے سے پہلے اُس کی تردید شروع کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیرؤوں کے دل میں بھی اس حملہ آور کے مذہب کی نسبت بُغض پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح ٹھنڈے دل سے مختلف مذاہب پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا.اور بِلا غور کئے تمام مذاہب کے پیرو صرف دشمنوں کی روایات کی بنا پر دوسرے مذاہب کے عقائد کو بعیداز عقل اور مجموعۂ توہمات اور اُس کے احکام کو ناقابلِ عمل اور دنیا کے امن کے منافی خیال کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں اُن مذاہب سے نفرت کرنے لگتے ہیں.لیکن اگرہمدردانہ غور ہو تو ہر ایک مذہب میں بہت کچھ خوبیاں اور کسی قدر کمزوریاں نظر آئیںگی سوائے اس ایک سچے مذہب کے جو سب نقصوں سے پاک ہوتاہے.پس اس غور کا لازمی نتیجہ باہمی صلح اور آشتی ہوگا.ایک دوسرے کے مذہب پر ناجائز حملہ کرنے کی عادت لوگوں کو اس قدر پڑ گئی ہے کہ اس زمانہ میں وہ ایک شغل خیال کیا جاتا ہے حالانکہ اِس کے نتائج بحیثیت مجموعی تمام دنیا کے لئے خطرناک ہیں اور قرآن کریم نے اصولی طور پر اس آیت میں اسی نقص کے ازالہ کی طرف توجہ دلائی ہے.افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اسلامی فرقوں کا بھی یہی حال ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک خدا پرایمان رکھتے ہیں.ایک کتاب پر ایمان رکھتے
Page 410
وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۰۰۱۱۵ میں (بھی) ان کے لئے بڑا عذاب (مقدر) ہے.تفسیر.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مساجد میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے دے اور اُس کی عبادت سے لوگوں کو رو کے اور اس طرح اُن کو ویران کرنے کی کوشش کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے.یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے جو اسلام نے پیش کی ہے.اِسے سامنے رکھ لو دنیا کا کوئی مذہب اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا.مسلمانوں کا عمل جانے دو بلکہ اس حکم اور تعلیم کو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کا حق نہیں کہ ذکر الہٰی سے کسی کو روکے.اگر کوئی شخص مسجد میں جا کر ذکر الٰہی کرنا چاہے یا اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا چاہے تو اس سے روکنا بالکل ناجائز ہے.کوئی ہندو، سکھ یا عیسائی آجائے اور مسلمانوں کی مسجد میں اپنے رنگ میں عبادت الٰہی کرنا چاہے تو کسی مسلمان کو اُسے روکنے کا حق نہیں.اگر کوئی کہے کہ باجابجانا اور ناچنا اُن کی عبادت میں شامل ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کام وہ باہر کر لیں.جتنا حصہ ذکر الہٰی کا ہے وہ مسجد میں آکر ادا کرلیں.اِس آیت میں ان تمام قسم کی زیادتیوں اور تعدّیوں کو جو ایک مذہب کے پیرو دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں یا عبادات کے متعلق کرتے ہیں یک قلم موقوف کر دیا ہے اور سب مذاہب کے پیرؤوں کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ عبادت خانوں اور عبادتوں کے متعلق اپنے دلوں اور اپنے حوصلوں کو وسیع کریں کیونکہ اُن کا موجودہ طریق عمل نہایت ظالمانہ اور جابرانہ ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا.وہ ظالمانہ طریق جو عبادت خانوں یا عبادات کے متعلق زمانہ نزولِ قرآن کے وقت برتے جاتے تھے یا اب بھی برتے جاتے ہیں اور جن سے قرآن کریم منع فرماتا ہے یہ ہیں:.اوّل.اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر فتح پا تا تو اُس کے عبادت خانوں کو گِرا دیتا یا انہیں مقفّل کر دیتا یا اس مذہب کے پیرؤوں کو اُس میں عبادت نہ کرنے دیتا.دوم.ہر مذہب کے پیرو اپنی اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے مذاہب کے لوگوں کو عبادت کرنے سے روکتے اور ان میں دوسروں کو داخل ہونے تک کی بھی اجازت نہ دیتے.یہ باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے وقت میں بڑے زور سے رائج تھیں اور مختلف مذاہب کے پیرؤوں کی عادت میں داخل ہو گئی تھیںاور اُس زمانہ میں یہ باتیں عیب نہیں بلکہ حق اور ضروری سمجھی جاتی تھیں اور تاریخ عالم بتاتی ہے کہ یہ اس زمانہ کی ایجاد نہ تھی بلکہ ہمیشہ سے دنیا انہی اُمور کی خوگر چلی آتی تھی.اِس لئے کسی انسان کی طبیعت اِن سے گھبراتی نہ تھی بلکہ اس زمانہ میں بھی ایک یا
Page 411
دوسری شکل میں یہ سب باتیں دنیا میں رائج ہیں اور گو علوم کی ترقی نے عبادت خانوں کو گرادینا یا ان کو بند کر دینا بڑی حد تک دُور کر دیا ہے لیکن اپنی عبادت گاہوں میں دوسرے مذاہب کے پیرؤوں کو عبادت کرنے کی اجازت نہ دینا تو اس زمانہ میں بھی ایک عام بات ہے.ایک مسیحی گرجا میں ایک مسلمان کواور ایک یہودی گرجا میں ایک مسیحی کو اور ایک مندر میں ایک مسیحی کو اور ایک پارسی صومعہ میںایک ہندو کو اپنی عبادت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جاتی اور اگر کوئی ایسا کرے تو یورپ کے علوم وفنون سے آگاہ ممالک سے لے کر افریقہ کے نیم وحشی قبائل تک کے لوگ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے.بلکہ بعض تو اپنے عبادت خانوں میں دوسروں کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے.قرآن کریم اس ظالمانہ کارروائی سے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ گو خیالات متفرق ہیں لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اُس کو اُس شہنشاہِ حقیقی کے نام لینے اور اُس کی عبادت کرنے سے روکنا یا مساجد میں کسی کو نہ آنے دینا اور اِ س طرح اُن کو ویران کرنے کی کوشش کرنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا بلکہ ایک بہت بڑا ظلم ہے.ہر ایک مذہب کے پیرؤ وں کو خواہ وہ مفتوح ہوں یا فاتح مساجد کے استعمال کی کامل آزادی ہونی چاہیے.اور اگر ایک مذہب کے عبادت خانہ میں کسی دوسرے مذہب کا کوئی انسان اپنے طریق پر خدا تعالیٰ کا نام لینا چاہے اور اُس کی عبادت کرنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے.کیونکہ مساجد ایک ایسا مقام ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں.پس اِن کے بارے میں انسان کو ڈر کر کام کرنا چاہیے اور آپس کے اختلافات کو اُن تک وسیع نہیں کرنا چاہیے ورنہ جو لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گےاور اس عمل میں غلوّ سے کام لیں گے اِس دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی وہ سزا سے بچ نہیں سکتے.یہ وہ تعلیم ہے جو قرآن کریم نے مختلف مذاہب کے معبدوں کے احترام اور اُن کی عبادت کے متعلق دی ہے.کسی اور مذہب کی تعلیم کو اس سے ملا کر دیکھو اور مقابلہ کرو کہ وہ کونسی تعلیم ہے جو ایک طرف تو عقل اور فہم کے مطابق ہے اور دوسری طرف دنیا میں امن قائم کرنے والی ہے.اس تعلیم کے ہوتے ہوئے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ایک متعصب مذہب ہے.مگر یہ اعتراض تبھی قابلِ قبول ہو سکتا ہے جب اس سے بڑھ کر عمدہ اور لطیف تعلیم دنیا میں کسی اور مذہب کی طرف سے پیش کی جائے.ورنہ زبانی اعتراض تو ہر مذہب کے لوگ دوسروں پر کر سکتے ہیں.دعویٰ بِلا دلیل بجائے نفع دینے کے عقلمندوں کی نظر میں انسان کو ذلیل کر دیتا ہے.ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وسعتِ حوصلہ جس کی تعلیم اسلام نے دی ہے.اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں کر سکتا.چنانچہ سب سے پہلا انسان جس نے اِس پر عمل کیا وہ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے نجران کے مسیحیوں کو اپنی مسجد میں گرجا کرنے کی اجازت دے دی.زادالمعاد میں لکھا ہے.لَمَّا قَدِ مَ
Page 412
وَفْدُ نَجْرَانَ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ دَخَلُوْاعَلَیْہِ مَسْجِدَہٗ بَعْدَ صَلٰوۃِ الْعَصْرِ فَحَانَتْ صَلَاتُھُمْ فَقَامُوْاأَ یُصَلُّوْنَ فِیْ مَسْجِدِہٖ فَاَرَادَ النَّاسُ مَنْعَھُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ’’ دَعُوْھُمْ‘‘ فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ فَصَلُّوْا صَلَاتَـھُمْ (زادالمعاد،فصل فی قدوم وفد نجران علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ) یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے پاس نجران کا عیسائی وفد آیا.تو وہ لوگ عصر کے بعد مسجد نبویؐ میں آئے اور گفتگو کرتے رہے.گفتگوکرتے کرتے اُن کی عبادت کا وقت آگیا(غالباً وہ اتوار کا دن ہو گا) چنانچہ وہ وہیں مسجدمیں اپنے طریق کے مطابق عبادت کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے.لوگوں نے چاہا کہ وہ انہیں روک دیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا ’’ ایسا مت کرو‘‘.چنانچہ انہوں نے اُسی جگہ مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنے طریق کے مطابق عبادت کر لی.پس مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے کا کسی کو حق نہیں.اگر تمام اقوام اس بات پر عمل کرنے لگ جائیں تو تمام باہمی جھگڑے ختم ہو جائیں.اگر ہر قوم اپنے معبد میں دوسروں کو آنے اور وہاں عبادت اور ذکر الہٰی کرنے کی اجازت دے دے تو کبھی آپس میں مناقشت اور جھگڑا پیدا نہ ہو اور دنیا میں ہر طرف امن قائم ہو جائے.مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے اعمال پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا وہ اس تعلیم پر پوری طرح عمل کرتے ہیں جو قرآن کریم دیتا ہے.اور جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا یا اس کے خلاف اپنے خود ساختہ اصول پر عمل کر رہے ہیں.میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت غیر احمدیوں اور ہم میں ایک فیصلہ کن آیت ہے.قرآن کریم میں مَنْ اَظْلَمُ کے الفاظ تین قسم کے لوگوں کے لئے آئے ہیں.اول جھوٹے مدعیان نبوت کے لئے.دومؔ سچے نبی کو جھوٹا کہنے والے کے لئے.جیسا کہ آتا ہے.فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ (یونس :۱۸) کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افترا کرتا ہے یا سچے نبی کے الہام کو جھٹلاتا ہے اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے.سوم.مساجد میں عبادت الہٰی سے روکنے والوں کے متعلق جیسا کہ اس جگہ ہے اَب سوال یہ ہے کہ آیا بانیء سلسلہ احمدیہ نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا ہے یا غیر احمدی ایک سچے نبی کے منکر ہیں ؟ بہرحال دونوں میں سے ایک مَنْ اَظْلَمُ میں ضرور شامل ہے.اِس سوال کو یہ تیسری آیت بالکل حل کر دیتی ہے کیونکہ جہاں جماعت احمدیہ میں ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ اس نے اپنی مساجد میں کسی کو عبادت کرنے سے روکا ہو وہاں مسلمانوں میں ایسی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کے افراد کو اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھنے سے روکا اور اُن پر سختیاں کیں.پس اس آیت نے ثابت کر دیا کہ بانیء سلسلہ احمدیہ کے مخالفین اپنے عمل
Page 413
کے لحاظ سے اس گروہ میں شامل ہیں جس کے متعلق مَنْ اَظْلَمُکے الفاظ آتے ہیں اور جو خدائی منشاء کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں.اُولٰٓىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآىِٕفِيْنَ.فرماتا ہے کہ کیسے تعجب کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا گھر ہو اور پھر یہ ذلیل لڑائیاں ہوں.حالانکہ اُن کے لئے یہ ہر گز مناسب نہ تھا کہ اس قسم کی ظالمانہ حرکت کرتے.یا ان کا کوئی حق نہ تھا کہ خدا تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرنے سے دوسروں کو روکتے.ان کو تو چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کے گھر جاتے وقت خوف سے اُن کا دل لرزتا اور اس قسم کے فسادات پر کمربستہ نہ ہوتے.لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ ہمارے گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم بھی ان کے گھروں کو برباد کر دیںگے اور یہ دنیا میں بھی رُسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی انہیں عذاب عظیم ملے گا.کیونکہ جنّت خدا تعالیٰ کا گھر ہے جس کا ظل مسجد ہے.جب انہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تو ان کو اگلے جہان میںکہاں امن میسر آسکتا ہے.مگر اس کے یہ معنے نہیںکہ مساجد کی پناہ میں آنے والے لوگوں کو اسلامی شریعت نے قانون سے بالا سمجھا ہے.اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ(رکوع۱۳) میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حکومتِ وقت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖ وسلم اور آپ کی جماعت کے خلاف خفیہ کارروائیاں کرنے کے لئے ایک مسجد تیار کی تھی اور خودرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست بھی کی تھی کہ آپ تشریف لا کر اس میں نماز پڑھیں اور دُعا فرمائیں.مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر حقیقت کھول دی اور بتادیا کہ اِن لوگوں نے یہ مسجد صرف اس لئے تیار کی ہے کہ ان کی منافقت پر پردہ پڑا رہے اور یہ لوگ یہاںجمع ہو کر اسلام کے خلاف منصوبے کرتے رہیں اور مسلمانوں کو تباہ کریں.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا اور اس کی جگہ کھاد کا ڈھیر لگوادیا.پس مسجد اپنی ذات میں کسی مجرم کو نہیں بچا سکتی.اگر مسجد میں کوئی بُرا کام کیا جائے گا تو اس کو بُرا سمجھا جائے گا اور اگر اچھا کام کیاجائے گا تو اس کو اچھا سمجھا جائے گا بلکہ اور مساجد تو الگ رہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ وہ کسی مجرم یا قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو پناہ نہیں دیتا اور نہ قتل کر کے بھاگنے والے کی پناہ گاہ بن سکتا ہے اور نہ چوری کر کے بھاگنے والے کو بچا سکتا ہے.بلکہ ایسے لوگ پکڑے جائیں گے اور انہیں قانونی گرفت میں لایا جائے گا.چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ اِبْنِ اَخْطَل جس کے قتل کا آپؐ نے حکم دیا تھا کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر کھڑا ہے تو آپؐ نے فرمایا اُسے وہیں قتل کر دو.چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا(السیرۃ الحلبیۃ باب ذکر مغاذیۃ ؐفتح مکۃ)
Page 414
پس اگر بعض مجرموں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بھی قتل کر دینے کا حکم دیا تھا تو دوسری مسجدوں کی خانہ کعبہ کے مقابلہ میں کیا حیثیت ہے کہ اُن میں خلاف آئین کام کرنے والے لوگوں کو قانون سے بالا سمجھا جائے.پس مساجد تقویٰ کے قیام کے لئے قائم کی گئی ہیں نہ کہ قانون شکنی کے لئے.اگر مسجد میں بھی قانون شکنی کے اڈے بن جائیں تو پھر شیطان کے لئے تو کوئی گھر بھی بند نہیں رہتا جن گھروں کو خدا تعالیٰ نے امن کے لئے، تسکینِ قلوب کے لئے، روحانیت کے لئے، تقویٰ کے قیام کے لئے، تعاون اور اتحاد باہمی کے لئے بنایا ہے ان گھروں کو مسلمانوں میں فتنہ ڈلوانے کا ذریعہ بنانا یا اُن گھروں کو حکومت سے بغاوت کرنے کا ذریعہ بنانا یا ان گھروں کو فتنہ و فساد کی بنیاد رکھنے کی جگہ بنانا ایک خطرناک ظلم ہے جس کی اسلام کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا.اِس آیت میں ان لوگوں کے لئے جو عبادت گاہوں میں خدا تعالیٰ کا نام بلند کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں.دو۲ سزائوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک یہ کہ انہیں دنیا میں ذ ّلت نصیب ہو گی اور دوسرے آخرت میں انہیں سخت سزا ملے گی.ذ ّلتکی سزا اس لحاظ سے تجویز کی گئی ہے کہ مساجد اور معابد بنانے کی صرف ایک ہی غرض ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ان میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی جائے.پس جو شخص اِن میں لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے وہ دنیا کی نگاہ میں اپنے لئے ذ ّلت اور رسوائی کے سامان پیدا کرتا ہے جو اس فعل کی ایک طبعی سزا ہے.یہ الفاظ مشرکین مکہ کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی پر بھی مشتمل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کعبہ میں داخل ہونے سے روکا اور آخر جب مکہ فتح ہوا تو انہیں ذ ّلت اور رسوائی کے عذاب سے دو چار ہونا پڑا.وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ١ۗ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ١ؕ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں.اس لئے جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی توجہ ہوگی.اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۰۰۱۱۶ اللہ (تعالیٰ) یقیناً وسعت دینے والا (اور) بڑا جاننے والا ہے.حَلّ لُغَات.وَجْہٌ کے تین معنے ہیں.(۱) نَفْسُ الشَّیْ ءِ یعنی کسی چیز کی ذات(۲)توجہ(۳) مُنہ.پس فَثَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ کے معنے ہوئے.اُدھر ہی اللہ کو پائو گے(۲)اُدھر ہی اللہ کی توجہ پائو گے(۳) اُدھر ہی اللہ کا مُنہ پائو گے.(اقرب)
Page 415
وَاسِعٌ.بڑی وسعت والا یا بڑی وسعت بخشنے والا.(اقرب) تفسیر.عیسائی لوگ جو ہمیشہ قرآن کریم پر کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں وہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے آہستہ آہستہ مسلمانوں کا قبلہ بدلا ہے اور زیادہ تر افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض مسلمان مفسرین نے بھی اپنی ناواقفیت کی وجہ سے انہیں اس اعتراض میں مدد دی ہے.حالانکہ یہ آیت اُن آیات میں سے سمجھی جاتی ہے جنہیں منسوخ قرار دیا جاتا ہے.وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ مشرق اور مغرب سب خدا کا ہے.اس لئے جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو پھر حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھو اور آخر میں یہ حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھو.گو یا اُن کے نزدیک یہ پہلی آیت ہے جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم جدھر چاہو منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو.لیکن پھر اسے منسوخ کر دیا گیا.حالانکہ اس آیت کا قبلہ کے ساتھ دُور کا بھی تعلق نہیں.نہ تو اس آیت میں نماز کا ذکر ہے اور نہ اس آیت سے پہلے اس کا کوئی ذکر ہے.ہاں مساجد کا ذکر ضرور آتا ہے مگر ان کے ذکر کے بعد لِلّٰہِ المَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کے کوئی معنے نہیں بنتے کیونکہ مساجد کے ذکر کے ساتھ ایک مخصوص جہت کی تعیین بھی ضروری تھی تاکہ سب مسلمان ایک طرف مُنہ کر کے نماز پڑھتے اور ایسا نہ ہو تاکہ کسی کا مُنہ ایک طرف ہوتا اور کسی کا دوسری طرف.مگر مساجد کے ذکر کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ مشرق و مغرب سب خدا کا ہے تم جدھر چاہو مُنہ کر لیا کرو.اور پھر اگلی آیت میں بھی نہ نماز کا ذکر آتا ہے اور نہ قبلہ کا پس یہ معنے کسی صورت میں بھی درست نہیں.اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی آیات سے یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصاریٰ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوائے ان کے کسی اور مذہب میں نجات نہیں اور مشرک جو کسی دین کے پابند نہیں یاد ہر یہ جو خدا تعالیٰ کے قائل نہیں.یہ لوگ بلاوجہ مسلمانوں کی عبادت گاہوںمیں دخل اندازی کرتے ہیں اور انہیں خدائے واحد کے آگے سر بسجود ہونے نہیں دیتے.اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیںاور چونکہ قاعدہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی سے کوئی دولت چھینتا ہے تو پھر کسی اور کو جو اس کا حقدار ہوتا ہے دے دیتاہے اور چونکہ اس قسم کے افعال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ ان کے اموال اور جائیدادیں چھین لی جائیں اور انہیں ذلیل کیا جائے.اس لئے لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم اپنی بے بسی پر غم نہ کھائو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے.ہم ان لوگوں سے حکومت چھین لیں گے اور اُن کی جگہ تمہیں مشرق و مغرب کا حکمران بنا دیں گے.
Page 417
اور ملک بھی فتح ہوںگے.یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جب مُٹھی بھر مسلمان ہر قسم کے مصائب میں سے گزررہے اور آزمائشوں میں ڈالے جا رہے تھے اور ان کا مستقبل سخت تاریک دکھائی دیتا تھا.لیکن یہ پیشگوئی جلد ہی فتح مکہ کی شکل میں پوری ہو گئی اور تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا.اور ایک صدی سے بھی کم عرصہ میں اسلام کا جھنڈا قریباً تمام ممالک میں لہرانا شروع ہو گیا.وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ کے الفاظ میں اِس طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلام کے لئے پہلے مشرق میں پھیلنا مقدر ہے اور پھر آخری زمانہ کے موعود کی بعثت کے بعد وہ مغرب میں بھی پھیل جائے گا.سو مغرب کو اس کے لئے تیار رہنا چاہیے کیونکہ و ہ زمانہ اب دُور نہیں.سورج نکل چکا ہے اور اس کی شعاعیں انہیں بیدار کر رہی ہیں.اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌبھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آیت کا قبلہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے.وہ جسے چاہے دولت میں بڑھاوے اور پھر وہ علیم بھی ہے.وہ جانتا ہے کہ کن لوگوں کے پاس لوگ سُکھ اور آرام پا سکتے ہیں.جس کے پاس رہ کر لوگوں کو آرام ملتا ہے اُسی کو حکومت ملا کرتی ہے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری جماعت کے متعلق بھی پیشگوئیاں ہیں کہ اُسے دنیوی ترقیات حاصل ہوں گی.مگر اللہ تعالیٰ دنیوی حکومتیں اُسی کو دیتا ہے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کر سکیں.پس تم بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نافع الناس وجود بنائو اگر تمہاری بھی وہی حالت ہو کہ خدا کے بندے تم سے دُکھ پائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہو گی کہ دنیا کی باگ ڈور تمہارے ہاتھ میں دی جائے.اور ایک ظالم کو بدل کر دوسرا ظالم کھڑا کر دیا جائے.وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا١ۙ سُبْحٰنَهٗ١ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے (اپنے لئے )ایک بیٹا بنا لیا ہے (ان کی بات درست نہیں) وہ (تو ہر کمزوری سے) پاک وَ الْاَرْضِ١ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ۰۰۱۱۷بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ١ؕ ہے.بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا ہے.سب اس کے فرمانبردار ہیں.وہ آسمانوں اور زمین کو (بغیر
Page 418
وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ۰۰۱۱۸ کسی سابق نمونہ کے) پیدا کرنے والا ہے.اور جب وہ کسی امر (کے عالمِ وجود میں لانے )کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے متعلق وہ صرف یہ کہتا ہے کہ تو ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے.حَلّ لُغَات.قَضٰی کے معنے ہیں (۱)خَلَقَ.اِن معنوں میں اس لفظ کا استعمال قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے.فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ (حٰم السّجدۃ:۱۳) یعنی جو دنیا اُس نے پیدا کی تھی اُسے اس نے سات آسمانوں کی صورت میں بنایا (۲) اَعْلَمَ یعنی اُس نے اُسے بتادیا.علم دے دیا.قرآن کریم میں آتا ہے.وَ قَضَيْنَاۤ اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ فِي الْكِتٰبِ (بنی اسراءیل:۵)ہم نے تورات میں بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی(۳) اَمَرَ حکم دیا.جیسے آتا ہے.وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ (بنی اسراءیل:۲۴) کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اُسی کی عبادت کرو.(۴) حجت پوری کر دینا.الزام قائم کر دینا.جیسے کہتے ہیں.قَضٰی عَلَیْہِ الْقَاضِیْ.قاضی نے اُس پر حجت قائم کر دی یا اُس کے متعلق فیصلہ کر دیا.(۵) پورا کر دینا.جیسے آتاہے.فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ(القصص:۳۰)جب موسیٰ ؑنے اپنی مقررہ مدت پوری کر دی(۶) ارادہ کرنا.جیسا کہ فرمایا.فَاِذَا قَضٰی اَمْرًا(البقرۃ:۱۱۸).جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے.(اقرب) اَمْرٌ کے بھی کئی معنے ہیں.(۱)دین جیسے ظَھَرَ اَمْرُ اللّٰہِ کے معنے ہیں اللہ کے احکام نازل ہو گئے(۲) بات جیسے آیت اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا(ھود:۴۱) میں ہے ہماری بات کے پورا ہونے کا وقت آگیا(۳) عذاب.جیسا کہ قُضِیَ الْاَمْرُ(البقرۃ:۲۱۱) میں ہے (۴) قَضٰی اَمْرًا کے معنے قرآن کریم سے الہامِ الہٰی کے نزول کے بھی معلوم ہوتے ہیں.ان معنوں کے علاوہ اس کے اور بھی کئی معنے ہیں.تفسیر.یہود کا یہ دعویٰ کہ نجات بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے گو ایک غلط دعویٰ تھا مگر اُن میں اتنی معقولیت ضرور پائی جاتی تھی کہ وہ دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتے تھے.مگر عیسائیوں کا یہ دعویٰ کہ نجات اُن سے مخصوص ہے نہ صرف ایک غلط دعویٰ ہے بلکہ اِس میں یہ غیرمعقولیت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اس دعویٰ کے باوجود دوسروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں اور انہیں اپنے مذہب کی دعوت دیتے ہیں اور پھر اِس غیر معقولیت کی بناء اس غیر معقول عقیدہ پر رکھتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ تھا اور اب وہی لوگ نجات پا سکتے ہیں جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں گے.اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں کئی دلائل دیتا ہے اور فرماتا ہے خداتعا لیٰ کے لئے کسی ولد کا ماننا اس لئے درست نہیں کہ وہ پاک ہے یعنی
Page 419
ولد کے ماننے سے اللہ تعالیٰ میں کئی نقائص ماننے پڑتے ہیں.اوّل.ولد کے لئے شہوت کا ہونا ضروری ہے اور شہوت دوسری چیز کی طرف توجہ کرنے اور اس کی احتیاج پردلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے.دوم.ولدکے لئے بیوی کا ہونا ضروری ہے اور یہ ایک اور احتیاج ہے جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے.سوم.بیٹے میں جزئیت ہوتی ہے یعنی وہ اپنے باپ کا جزو ہوتاہے اور اس کا خون اس میں شامل ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا بھی ولد تسلیم کیا جائے تو اُس کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ اُس کے اجزاء بھی تقسیم ہوئے.چہارم.بیٹا ماننے سے اُس کا فنا ہونا لازم آتا ہے کیونکہ بیٹے کی ضرورت ہمیشہ فانی وجودوں کو ہی ہوتی ہے ورنہ جو چیزیں اپنے مقصد پیدائش تک قائم رہنے والی ہیں اُن کو کسی قائم مقام کی ضرورت نہیں جیسے سورج، چاند، ستارے، آسمان اور زمین وغیرہ ہیں.یہ چیزیں چونکہ اُس وقت تک چلتی چلی جائیں گی جب تک کہ ان کی ضرورت قائم ہے.اس لئے نہ تو یہ فنا ہوتی ہیں اور نہ اُن کے کسی قائم مقام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن انسان چونکہ فنا ہو جاتا ہے اس لئے اسے قائم مقام کی بھی ضرورت ہوتی ہے پس اگر خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کیا جائے تو اس کے لئے بھی فنا ماننی پڑے گی.حالانکہ وہ اس نقص سے منزّہ ہے.دوسری بات لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ میں یہ بیان کی ہے کہ ایک بادشاہ کو بعض دفعہ بیٹے کی ایک اچھے مدد گار کے طور پر ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اُس کی سلطنت کو وسیع کر سکے.مگر خدا تعالیٰ کو کسی مددگار کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ مدد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ایسی چیز ذاتی کوشش سے حاصل نہ ہو سکے.مگر جب تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے تو پھر اُسے کسی مدد گار کی کیا ضرور ت ہے؟ بیٹے کی ضرورت تو تب ہو جب اُسے نئی فتوحات کی ضرورت ہو یا نئے ممالک پر حکمرانی کی خواہش ہو.لیکن جب ہر چیز اُسی کی پیدا کردہ ہے تو پھر اُس نے بیٹا کیسے بنا لیا؟ پھر بعض اوقات بادشاہ کو یہ مشکل پیش آجاتی ہے کہ ملک کا کوئی حصّہ باغی ہو جاتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے کہ سلطنت کے شورش زدہ یا دُور افتادہ علاقوں پر کنٹرول کرنے کے لئے کوئی دست و بازو بنے اور مدد گار کے طور پر کام آئے مگر اللہ تعالیٰ کی حکومت سے تو کوئی بھی باہر نہیں.کُلٌّ لَّہٗ قَانِتُوْنَ سب کے سب اس کے مطیع اور فرمانبردار ہیں.ایسی صورت میں اُس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اُس نے ایک شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر ہو سکتا تھاکہ کوئی کہہ دیتا کہ اَب تو اُس کا کام چل گیا ہے لیکن زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے وقت تو کام
Page 421
پھر فرمایا وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے ارادہ میں مزاحم نہیں ہو سکتی.وہ اِدھر کُنْ کہتا ہے اور اُدھر اس کا فیصلہ دنیا میں نافذ ہو جاتا ہے.اس میں ایک تو اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ نہ صرف پیدائشِ عالم خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بلکہ فنا بھی اُسی کے اختیار میں ہے اور اس غرض کے لئے بھی اُسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں.اس شبہ کا ازالہ اس لئے کیا گیا ہے کہ ممکن تھا بعض لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا کہ خدا تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا تو کر لیں اور وہ سب کی سب خدا تعالیٰ کے قانون کی بھی تابع ہیں لیکن ممکن ہے اس عالمِ موجودات کو فنا کرنے کے لئے اُسے کسی ساتھی اور مددگار کی ضرورت ہو.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا یہ خیال بھی درست نہیں.فنا بھی اُسی کے اختیار میں ہے پس اس غرض کے لئے بھی اُسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں.عیسائیت کے ذکر میں وَ اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ فرما کر عیسائیوں کے اس عقیدہ پر بھی ایک لطیف رنگ میں چوٹ کی گئی ہے کہ مسیح ؑ مصلوب ہو گیا تھا.فرماتا ہے جس خدا نے اپنے بیٹے کو جسے تم خدا تسلیم کر رہے ہو صلیب پر مار دیا اُسے دنیا کے فنا کرنے میں کیا مشکل پیش آسکتی ہے وہ سب کو آسانی سے موت کے گھاٹ اُتار سکتا ہے اور کوئی چیز اس کے فیصلہ میں روک نہیں بن سکتی.اِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ الہام الہٰی کا اجرا بھی خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور جب وہ کوئی نیا کلام دنیا میں نازل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے نزول کو روک نہیں سکتی.اس میں عیسائیوں کے اس نقطہ نگاہ کا ردّ کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح ؑ پر جو آخری الہام نازل ہونا تھا وہ ہو چکا اب آئندہ کے لئے کسی پر کوئی نیاالہام نازل نہیں ہوسکتا.مسیحی کتب میں حضرت مسیح ؑ کو کلام کہا گیا ہے اور قرآن کریم نے بھی ان کے لئے کلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے.عیسائی اس کے غلط معنے کرتے ہوئے کہاکرتے ہیں کہ کلمہ اور کلام کے چلے جانے کے بعد الہام کا سلسلہ بند ہوچکا ہے مگر فرمایا تمہارا یہ خیال غلط ہے.جس طرح وہ پہلے الہام الٰہی نازل کرتا رہا.اسی طرح وہ آئندہ بھی کرتا رہے گا.اور جس طرح پہلے روحانی نظام کے قیام کے لئے اُسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی اسی طرح آئندہ بھی اسے کسی بیٹے یا مددگار کی ضرورت نہیں.کُنْ فَیَکُوْنَ کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے یہ معنے نہیں کہ خدا تعالیٰ جب کسی چیز کا اردہ کرتا ہے تو وہ فوری طور پر ایک آن میں پیدا ہو جاتی ہے.بلکہ اس کے صرف یہ معنے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے اس امر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ انسانوں کی طرح حرکت کرے اور اس کام کے کرنے کے لئے چل کر
Page 422
جائے بلکہ وہ صرف یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ ایسا ہو جائے اور پھر کوئی چیز اس کے فیصلہ میں مزاحم نہیں ہوتی.اسی طرح یہ آیت کسی خاص وقت کے تعیّن پر بھی دلالت نہیں کرتی بلکہ کم یا زیادہ جتنا وقت بھی کسی چیز کی تکمیل کے لئے ضروری ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے بعد وہ اتنے عرصہ میں اپنی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے.غرض اِن آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ؑ کی ابنیت کی پانچ دلائل سے تردید کی ہے اور بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں وہ اس قسم کی تمام احتیاجوں سے بالا اور ارفع ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اناجیل میں مسیح کی نسبت خدا تعالیٰ کے بیٹے کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں لیکن بائیبل کا معمولی مطالعہ رکھنے والا انسان بھی جانتا ہے کہ یہود میں ابن اللہ کے معنے خدا کے پیارے یا اس کے نبی کے ہوتے ہیں.اور یہ لفظ متعدد مقامات پر اوروں کے لئے بھی استعمال ہوا ہے.اس میں مسیح ؑ کی کوئی خصوصیت نہیں.چنانچہ لوقاباب۲۰آیت۳۴ تا ۳۶ میں آتا ہے.’’ یسوع نے جواب میں اُن سے کہا اس جہان کے لوگ بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں لیکن جو لوگ اُس جہان کے اور قیامت کے شریک ہونے کے لائق ٹھہرتے نہ بیاہ کرتے ہیں اور نہ بیاہے جاتے.پھر نہیں مرنے کے.کیونکہ وے فرشتوں کی مانند ہیں.اور قیامت کے بیٹے ہو کر خدا کے بیٹے ہیں.‘‘ اس جگہ حضرت مسیح ؑنے ان تمام لوگوں کو جو اپنی زندگی دین کے لئے وقف کرتے ہیں خدا کے بیٹے قرار دیا ہے.اسی طرح متی باب ۵ آیت ۹ میں لکھا ہے.’’مبارک وے جو صلح کرانے والے ہیں کیونکہ وے خدا کے فرزند کہلائیں گے.‘‘ اس جگہ حضرت مسیح ؑ نے فرمایا ہے کہ صلح کرانے والے خدا کے فرزند کہلاتے ہیں.پھر متی باب۵ آیت۴۵ میں لکھا ہے.’’تاکہ تم اپنے باپ کے ، جو آسمان پر ہے فرزند ہو.‘‘ اس میں تمام مومنوں کو خدا تعالیٰ کا فرزند اور بیٹا کہا گیا ہے.متی باب۵ آیت۴۸ میں آتا ہے.’’پس تم کامل ہو.جیسا تمہارا باپ ،جو آسمان پر ہے کامل ہے.‘‘ اس میں بھی مسیح علیہ السلام سب مومنوں کو خدا کے بیٹے قرار دیتے ہیں.پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی سب مومنوں کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا گیا ہے.لکھا ہے.’’تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو.‘‘ (استثنا باب۱۴ آیت۱)
Page 423
خروج باب۴ آیت۲۲ میں آتا ہے.’’اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میراپلوٹھا ہے.‘‘ اس حوالہ کو مدّنظر رکھتے ہوئے تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا حق حضرت مسیح ؑکی بجائے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حاصل ہے کیونکہ وہ پلوٹھے ہیں اور حضرت مسیح بیٹے تھے.پلوٹھے کے ہوتے ہوئے بیٹے کا کیا حق تھا کہ وہ جائیداد پر قبضہ کرتا.غرض عہد عتیق اور عہد جدید دونوں کی رُو سے تمام مومن خدا کے فرزند ہیں.حضرت مسیح ؑ کی اس میں کوئی تخصیص نہیں.وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اور وہ لوگ جو (خدا تعالیٰ کی حکمتوں کا )علم نہیں رکھتے.کہتے ہیں کہ اللہ کیوں ہم سے (براہ راست ) بات نہیں کرتا اٰيَةٌ١ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ١ؕ یا(کیوں)ہمارے پاس کوئی نشان (نہیں ) آتا؟اسی طرح (بالکل) انہی کی سی بات (وہ بھی) کہا کرتے تھے جو تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ١ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ۰۰۱۱۹ ان سے پہلے (زمانہ کے)لوگ تھے.ان سب کے دل ہمرنگ ہوگئے ہیں.ہم تو ایسے لوگوں کے لئے جو یقین لے آتے ہیں ہر طرح کے نشانات کھول کر بیان کر چکے ہیں (مگر یہ لوگ مانتےنہیں).تفسیر.بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بغیر کسی حکمت کے یونہی ایک شخص کو نبی بنا کربھیج دیتا ہے اور وہ انتخاب میں کسی اہلیت کو مدنظر نہیں رکھتااور پھر اس غلط خیال کے نتیجے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں براہ راست کیوں حکم نہیں دے دیتا کہ ایسا کرو.اور ایسا نہ کرو.تاکہ کوئی جھگڑا ہی پیدا نہ ہو.آخر اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا اور اگر ہم اس بات کے مستحق نہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ باتیں کرے تو کم از کم یہ تو ہوناچاہیے تھا کہ کوئی دلیل ہی مہیا کر دی جاتی جس کی وجہ سے ہم اسے مجبوراً مان لیتے.میری تحقیق یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی کفار کے آیت طلب کرنے کا ذکر آتاہے وہاں اس سے مراد ہمیشہ عذاب ہی ہوتا ہے.بشرطیکہ اُس کےخلاف وہاں کوئی قرینہ موجود نہ ہو.چنانچہ وہ تمام مقامات جہاں کفار کی
Page 424
طرف سے آیت کا مطالبہ کیا گیا ہے اُن پر غور کر کے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہر جگہ آیت سے مراد عذاب ہی ہوتا ہے.اس جگہ بھی یہی مراد ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم پر نازل ہوتا اور ہم اسے مان لیتے.کیونکہ اگر یہ اس کا بندہ ہے تو ہم بھی اُسی کے بندے ہیں.پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے.اور اگر یہ کہو کہ تم اس کے بندے تو ہو مگر تم عذاب کے مستحق ہو تو ایسی صورت میں ہم پر عذاب نازل ہونا چاہیے.گویا دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہونی چاہیے.اگر ہم اُس کے بندے ہیں تو ہم پر بھی کلام نازل ہونا چاہیے اور اگر کہو کہ تم گندے ہو گئے ہو تو پھر ہمیں ہلاک کر دیناچاہیے.لیکن اگر وہ ہمیں ہلاک بھی نہیں کرتا تو اس کے معنے یہ ہیں کہ ہم گندے نہیںاس لئے ہم پر بھی کلام نازل ہونا چاہیے.محمد(صلی اللہ علیہ وآلہ ٖوسلم) کو ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے کہ صرف اُسی پر کلام نازل ہوتا ہے.كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح اُن لوگوں نے بھی جو اِن سے پہلے گذرے ہیں کہا تھا اور بالکل اِن کی بات کے مشابہ کہا تھا.اِس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کے مقابلہ میں ایک ہی قسم کے اعتراض ہوتے چلے آئے ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب منہاجِ نبوت کا ذکر فرمایا کرتے تودشمن چِڑ جاتے اور کہتے کہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا کیوں نام لیتے ہو.مولوی محمدعلی صاحب جو اُس وقت ریویو آف ریلیجنز کے ایڈیٹر تھے اِس کا یہ جواب دیا کرتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب انبیاء میں شامل ہیں.پس اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی مثال نہ دیں تو اور کس کی دیں.لیکن بعد میں وہی مولوی محمد علی صاحب کہنے لگے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا.یہ نیا عقیدہ ہے جو قادیان والوں نے ایجاد کر لیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کا اعتراض صحیح ہے تو پھر تمام انبیاء کی نبوتیں باطل ٹھہرتی ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تھا کہ اُن کو الہام ہوتا ہے تو اس وقت اوروں کو الہام نہیں ہوا بلکہ صرف موسیٰ ؑ کو ہوا.پھر باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یکدم تباہ بھی نہیں کیا.ہاں حجت کے بعد وہ ہلاک ہوئے اور وہ بھی آہستہ آہستہ.اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب الہام ہوا تو اُن کے زمانہ میں بھی باقی لوگوں کو الہام نہیں ہوا اور پھر باقی لوگوں کو یکدم تباہ بھی نہیں کیا گیا پس اگر یہ دلیل صحیح ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ہم پر الہام نازل کرے اور اگر ہم الہام کے مستحق نہیں تو ہمیں تباہ کر دے تو اس دلیل کو پہلوں پر چسپاں کر کے دیکھ لو کہ کیا یہ صحیح قرار پاتی ہے یا غلط ؟ اور اگر تمہاری یہ دلیل پہلوں پر چسپاں نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ تمہارا یہ مطالبہ منہاجِ نبوت کے خلاف ہے.اصل بات یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کوئی جواب بن نہ آئے تو وہ آگے سے ایسا عذر تلاش کرتا ہے جس پر
Page 425
بحث ختم ہو کر اس کا پیچھا چُھوٹے.سچے نبیوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے یہ طریق اختیار کیا جاتا رہا ہے جب اُن کے مخالفوں کو اُن سے بحث کرنے میں ندامت ہوئی ہے تو فوراً انہوں نے ایسے مطالبات پیش کر دیئے ہیں کہ جن کی نسبت اُن کو یقین تھا کہ ایک یا دوسری وجہ سے اُن کا پورا ہونا ناممکن ہے.کبھی تو سنت اللہ کے خلاف کسی بات کا مطالبہ کر دیتے کبھی کسی دیر میں ہونے والی بات کو فوراً پورا کرنے کا مطالبہ کرتے.کبھی ایسے امر کا مطالبہ کرتے جو خلافِ شان الٰہی ہوتا اور پھر علاوہ اس قسم کے مطالبات کے یہ جواب بھی دیا کرتے کہ اچھا ہم لوگ جھوٹے ہیں تو عذاب الٰہی کیوں نہیں آتا.ہم پر عذاب الہٰی نازل ہو تب ہم مانیں گے ورنہ نہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بھی اِس سلوک میں دوسرے نبیوں سے مستثنیٰ نہ تھے بلکہ جس قدر آپ کا درجہ بلند تھا اُسی قدر آپؐسے آپؐ کے دشمنوں نے زیادہ غیر معقولیت کے ساتھ معاملہ کیا.جب اُن کو کوئی جواب نہ آتا تو قسم قسم کے سوال کرتے جن میں سے دو اس جگہ بیان کئے گئے ہیں.ایک تو یہ کہ اگر سچے ہو تو خدا تعالیٰ ہم سے خود کلام کرے اور ہم سے کہے کہ یہ شخص سچا ہے اس کو مان لو.حالانکہ خدا تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کے زمانہ میں یہ نہیں کیا کہ ملک کے ہر آدمی کو الہام ہوا ہو کہ فلاں شخص سچا ہے اسے مان لو.یہ تو ہو جاتا ہے کہ بعض اشخاص کو خدا تعالیٰ رؤیا اور کشوف کے ذریعہ بتا دیتا ہے کہ یہ مامور سچا ہے مگر سب لوگوں کو بتانا اس کی سنت کے خلاف ہے اور جن کو بتاتا ہے اُن کی شہادت سے لوگ فائدہ نہیں اُٹھاتے بلکہ اُن پر بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ بھی منصوبوں میں شامل ہیں.پھر سب کو الہام ہونا اس لئے بھی بے فائدہ ہے کہ ایمان تبھی مفیدہوتا ہے جبکہ وہ انسان کو کوشش سے حاصل ہو.اگر خدا تعالیٰ کا کلام سب پر نازل ہو تو پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں رہتا.اور انسان کی پیدائش کی اصل غرض فوت ہو جاتی ہے اور دوسری مخلوق اور انسان میں کچھ فرق نہیں رہتا.پس فرمایا کہ یہ لوگ سنت اللہ سے واقف نہیں اور نہیں جانتے کہ ایمان کس صورت میں نافع ہوتا ہے.کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے کلام کرے.حالانکہ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو پہلے نبیوں سے بھی ہوتا رہا ہے جن کو یہ مانتے ہیں لیکن انہوں نے اسے پورا نہیں کیا.پھر اس نظیر کے موجود ہوتے ہوئے اس رسول سے کیوں ایسا مطالبہ کرتے ہیں.درحقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل پہلے انبیاء کے منکرین کے دِلوں کے مشابہ ہو گئے ہیں.دوسرا مطالبہ یہ بیان کیا کہ ہمیں کوئی آیت دکھائو.اس کا جواب یہ دیا کہ ایسی آیات تو ہم دکھا چکے ہیں جن سے اگر کوئی فائدہ اٹھانے والا انسان ہو تو فائدہ اُٹھا سکتا ہے.لیکن جن لوگوں نے ضِد سے کام لینا ہو اور ہٹ پر قائم رہنا ہواُن کا کوئی علاج نہیں.اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں تو آیت کا لفظ اللہ تعالیٰ اور اُس کے انبیاء اور مومنوں
Page 426
کی طرف سے استعمال کیا گیا ہے وہاں تو اس کے معنے عام ہوتے ہیں یعنی کوئی نشان جو کسی صداقت پر دلیل ہو.خواہ وہ عذاب ہو یا انعام.خواہ کوئی ایسا نشان ہو جو اِن دونوں قسموں میں سے نہ ہو اور صرف ایک علامت کے طور پر ہو.لیکن جب کفار کے مُنہ سے یہ لفظ بیان کیا جائے تو اس کے معنے جیسا کہ اوپر بتایا جاچکا ہے ہمیشہ عذاب کے ہوتے ہیں پس تَاْتِیْنَااٰیَۃ سے مراد یہ ہے کہ ہم پر ایسا عذاب نازل ہو جو ہمیں تباہ کر دے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں تمہارا یہی کام تھا کہ تم اس قسم کے اعتراض کرتے اس لئے کہ جن لوگوں کے تم جانشین ہو وہ بھی یہی کہتے آئے ہیں.کیونکہ جس طرح نبی کا نبی مثیل ہوتا ہے اسی طرح اس نبی کے وقت کے کافر پہلے نبیوں کے کافروں کے مثیل ہوتے ہیں.پس اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی نشان نہیں دکھایا تو ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ ؑ کے دشمنوں کے مثیل تھے اور اگر حضرت عیسیٰ ؑ کو اُن کے دشمن کہتے تھے کہ یہ کوئی نشان نہیں لایا تو سچ کہتے تھے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ ؑ کے دشمنوں کے مثیل تھے.اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اُن کے مخالفوں نے یہی کہا تو ان کا کہنا حق تھا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کے مثیل تھے اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اُن کے نہ ماننے والوں نے یہ کہا تو اُن کا حق تھا کیونکہ وہ حضرت نوح ؑ کے دشمنوں کے مثیل تھے.خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِن کے دل مل گئے ہیں.اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی نشان نہیں لایا.حالانکہ ماننے والوں کے لئے بہتیرے نشان ہیں.ہاں نہ ماننے والوں کے لئے کوئی نہیں.تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْسے ظاہر ہے کہ انبیاء کی جماعتوں اور اُن کے مخالفین کا ایک ہی طریق عمل ہوتا ہے نبیوں کی مشابہت نبیوں سے.اُن کی جماعتوں کی مشابہت پہلی جماعتوں سے.اور اُن کے مکفرین کی مشابہت پہلے مکفرین سے ہوتی ہے.جس طرح انبیاء اور اُن کی جماعتیں ایک ہی راستہ پر قدم مارتی چلی جاتی ہیں اسی طرح ان کے مخالفین بھی اپنے پیشروؤں کی سنتوں پر عامل ہوتے ہیں خصوصاً جن انبیاء کی آپس میں مشابہت اور مماثلت ہو اور ایک ہی قسم کے کام ان کے سپرد ہوں اُن کے حالات تو آپس میں بہت ہی ملتے جلتے ہیں.قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ میں بتایا کہ عذاب تو تم صداقت معلوم کرنے کے لئے مانگتے ہو حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سی آیات ظاہر کر دی ہیں جو اس رسول کی صداقت ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں بشرطیکہ تمہاری نیت ماننے کی ہو اور تم ضِد اورتعصب سے کام نہ لو.پس اگر تمہارا مطالبہ دیانت داری پر مبنی ہے تو تم اُن دلائل و براہین پر کیوں غور نہیں کرتے اور صرف عذاب کا مطالبہ ہی کیوں کرتے ہو.اگر انبیاء کی بعثت کی غرض یہ ہوتی کہ لوگوں کو تباہ کیا جائے تو اِدھر نبی آتا اور اُدھر خدا تعالیٰ تمام منکروں کو تباہ کر دیتا.لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر مانتا کون؟ اس لئے
Page 427
اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انبیاء کی بعثت کے بعد پہلے رحمت کی آیات ظاہر ہوتی ہیں تاکہ جس نے ماننا ہو مان لے اور پھر جو ضِدی طبع نہیں مانتے اُن پر عذاب آجاتا ہے.اس آیت میں لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف فرمایا ہے کہ نشان تو بہت ظاہر ہو چکے ہیں مگر جو شخص ہر بات میں شبہ پیدا کرے اُسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے.اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی شکی طبیعت کو چھوڑواوریقین کا مادہ پیدا کرو.ورنہ جو لوگ صرف یہی کہنا جانتے ہیں کہ’’ اور نشان دکھائو‘‘ اُن کے لئے کہاں سے نشان آسکتے ہیں.ہماری زبان میں بھی مشہور ہے کہ سوتے کو سب جگا سکتے ہیں لیکن جاگتے کو کوئی نہیں جگا سکتا.اسی طرح جو لوگ ہر نشان کا انکار کر دیں اُن کے لئے کوئی نشان بھی ہدایت کا موجب نہیں بن سکتا.یہاں آیات سے قرآن کریم کی آیات مراد نہیں بلکہ ہر قسم کے دلائل اور براہین مراد ہیں جو کسی نبی کی صداقت ثابت کرنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں.اس آیت نے عیسائیوں کے اس اعتراض کو بھی باطل کر دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے کوئی نشان نہیں دکھایا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یقین رکھنے والی قوم کے لئے ہر قسم کے نشانات کھول کر بیان کر چکے ہیں.اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا١ۙ وَّ لَا تُسْـَٔلُ عَنْ ہم نے یقیناًتجھے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا (بنا کر) حق (اور راستی) کے ساتھ بھیجا ہے.اور دوزخیوں کے اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ۰۰۱۲۰ متعلق تجھ سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی.حَلّ لُغَات.بِالْحَقِّ میں باء کے معنے ساتھ اور معیت کے ہیں.بِالْحَقِّ اس جگہ حال واقع ہوا ہے اور حال فاعل کا بھی ہو سکتا ہے اور مفعول کا بھی.اس جگہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں.(إِمْلَاءمَا مَنّ بِہِ الرَّحْمٰن) تفسیر.قرآن کریم کے معانی کے متعلق یہ اصول ہے کہ اگر کسی آیت کے کئی معنے ہوں اور وہ معنے دوسری آیات کے خلاف نہ ہوں تو وہ سارے کے سارے معنے چسپاں کئے جا سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم جن معنوں کو ردّ کرنا چاہتاہے اُن کو دوسری جگہ ردّ کر دیتا ہے لیکن جو معنے قرآن کریم کی کسی اور آیت سے ردّ نہ ہوں وہ تمام کے تمام چسپاں ہو سکتے ہیں.یہاں بھی بِالْحَقِّ کے چار معنے ہو سکتے ہیں.
Page 428
اگراسے فاعل کا حال قرار دیا جائے تو اس کے معنے یہ ہونگے کہ ہم نے تجھے ایسی حالت میں بھیجا ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے.اس کے آگے دو۲ مفہوم ہیں ایک یہ کہ ہم نے تجھے ایسے حال میں بھیجا ہے کہ حق کا خزانہ صرف ہمارے ہی پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں.اگر کوئی اور شخص تعلیم بنا کر پیش کرتا تو اس میں کئی قسم کی غلطیوں کی آمیزش ہوتی اور وہ دنیا کو تباہ کر دیتی.پس خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی ایسی سچی تعلیم نہیں دے سکتا تھا جس میں جھوٹ کی کوئی ملونی نہ ہوتی.اگر اور کوئی تعلیم دیتا تو یقیناً اُس میں دانستہ یا نادانستہ کئی قسم کی غلطیاں ہوتیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے بھیجا ہے اور ایسے حال میں بھیجا ہے کہ ہمارے پاس حق ہے.سچائی کا خزانہ ہمارے پاس ہے.اس لئے ہمارا ہی حق تھا کہ ہم تعلیم بھیجتے.کسی دوسرے کا حق نہیں تھا کہ وہ بھیجتا.اگر کسی دوسرے کی طرف سے تعلیم آتی تو وہ دنیا کو تباہ کر دیتی.کیونکہ اس میں جھوٹ کی ملونی ہوتی یا اس میں غلطیاں ہوتیں مگر جو تعلیم ہماری طرف سے آتی ہے وہ تباہی والی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ حقیقی اور سچی تعلیم ہوتی ہے اور وہی دوسروں کو حقیقی ہدایت دے سکتی ہے.پس یہ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم لوگوں کو ہدایت کی تعلیم دیں.بَالْحَقِّ کے دوسرے معنے مَعَ الْحَقِّ کے بھی ہو سکتے ہیں.اس لحاظ سے اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ ّّ کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم نے تجھے بھیجا ہے اور اس حال میں بھیجا ہے کہ ہم ہی اسے بھیجنے کے حقدار تھے.گویا جس طرح ہم بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ہیں اسی طرح ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ یہ تعلیم بھیجتے.آخر جس نے اس نظام کو پیدا کیا ہے اُسی کا حق ہے کہ وہ حکم دے دوسرے کا کیا حق ہے کہ وہ اس میں دخل دے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس تعلیم کو بھیجنے کے حقدارتھے کیونکہ ہم خالق اور مالک ہیں.آریہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ رُوح و مادہ کا خالق نہیں لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ قانون بناتا ہے حالانکہ جب وہ خالق نہیں تو اس کا کیا حق ہے کہ وہ قانون بنائے.پس فرمایا کہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم قانون بنائیں کیونکہ ہم خالق و مالک ہیں.اور جو خالق و مالک ہو وہ حق رکھتا ہے کہ اپنی مخلوق کے لئے قانون بنائے کیونکہ وہی مخلوق کی ضرورتوں کو جانتا ہے.جس نے پیدا ہی نہیں کیا اُسے کیا معلوم کہ انسانی قلب میں کیا کیا جذبات اُٹھتے ہیں.اوراسے کیا معلوم کہ کونسی باتیں اچھی ہیں اور کونسی بُری.اس لئے یقیناً وہ غلط قانون بنائے گا جو لوگوں کی ٹھوکر کا موجب ہو گا.پھر مفعول کے لحاظ سے بھی اس کے دو۲ معنیٰ ہیں.ایک یہ کہ ہم نے اس حالت میں تجھے بھیجا ہے کہ تیرے ساتھ سچ ہے.اگر انسانی تعلیم ہوتی تو اُس میں غلطی یا جھوٹ کا امکان ہوتا یا کوئی اور نقص ہوتا.مگر جو تعلیم تیرے پاس ہے وہ ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے اور جب وہ بالکل پاک ہے تو ماننا پڑے گا کہ وہ ہماری طرف سے ہے.
Page 429
دوسرے معنے یہ ہیں کہ ہم نے تجھے اس حال میں بھیجا ہے کہ تو ہی اس بات کا حق دار تھا کہ تجھے بھیجا جاتا اور تجھ پر کلامِ الہٰی نازل ہوتا.یہ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ کا جواب ہے.فرماتا ہے کہ چونکہ تو ہی حقدار تھا اس لئے ہم نے تجھے بھیج دیا.وہ لوگ حقدار نہ تھے.اگر وہ حقدار ہوتے تو ہم ان کا حق انہیں دے دیتے اور انہیں بھیج دیتے.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی لوگ پھر کس درجہ میں ہیں؟ سواس کے متعلق فرماتا ہے کہ باقی دو۲ درجوں میں ہیں.اول اگر وہ اس مستحق شخص کے ذریعہ اس کلام کو مان لیں گے تو بشارات سے حصہ لیں گے.دوم اگر وہ نہیں مانیں گے تو منکرین میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ کے عذاب سے حصہ پائیں گے.اسی لئے فرمایا کہ تو بشیر اور نذیر ہے.یعنی کچھ لوگوں کے لئے تو بشارتیں لایا ہے اور کچھ لوگوں کے لئے انذار لایا ہے یہ دو قسم کی آیات ہیں جو بعض کو بچانے والی اور بعض کو تباہ کرنے والی ہیں.بشارت والی آیات پہلے ہوتی ہیں اور انذار والی آیات پیچھے ہوتی ہے.پہلے ُتو بشیر ہے اس لئے پہلے بشارت والی آیات آئیں گی پھر ُ تو نذیر ہے جس کے نتیجہ میں انذار والی آیات آئیں گی.یہ قانونِ قدرت ہے کہ اگر بعض کو بچانا اور بعض کو تباہ کرنا ہو تو پہلے بچانے والی آیات کا ظہور ہوتا ہے تاکہ جنہوں نے بچنا ہے وہ بچالئے جائیں.غرض فرماتا ہے.اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! تیرے تین مقامات ہیں.اول : تجھے اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ کا مقام حاصل ہے.دوم : بشیر ہونے کا مقام حاصل ہے جس کا تعلق اُن بندوں سے ہے جو ایمان کی وجہ سے بچائے جاتے ہیں.سوم : نذیر ہونے کا مقام ہے جس کا اُن بندوں سے تعلق ہے جو انکار کرنے کی وجہ سے تباہ کر دیئے جاتے ہیں.بِالْحَقِّ کے ماتحت تجھ پر آیات کا نزول ہوتا ہے.بشیر ہونے کی وجہ سے رحمت کی آیات کا نزول ہوگا اور پھر نذیر ہونے کی وجہ سے عذاب اور تباہی والی آیات کا نزول ہو گا.وَ لَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ.فرماتا ہے ہمارارسول صرف کلامِ الٰہی پہنچانے کا ذمہ دار ہے.لوگوں سے منوانا اس کا کام نہیں اگر وہ سب لوگوں کو نہ منوا سکے اور کچھ لوگ رہ جائیں اور اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کے موردبن جائیں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ وہ سب کی نجات کا ٹھیکیدار نہیں.وہ تو مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے جو اس کے ذریعہ مان لیں گے وہ بچالئے جائیں گے اور نہ ماننے والے آہستہ آہستہ تباہ کر دیئے جائیں گے.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس حق ہے اور تیرے ماننے والوں کے لئے کامیابی اور تیرے منکروں کے لئے تباہی اور ناکامی مقدر ہے.اور یہ وہ نشانات ہیں جو تیری صداقت کے لئے ظاہر کئے گئے
Page 430
ہیں مگر دلیل اس کے لئے کافی ہوتی ہے جو ماننے کے لئے تیار ہو.لیکن جو شخص یہ کہتا ہو کہ خواہ کچھ ہومیں نے ماننا ہی نہیں اس کو دلیل کچھ کام نہیں دیتی.جیسا کہ یہود کے دو علماء ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے پاس آئے جب واپس گئے تو اُن میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اُس نے کہا معلوم تو سچا ہی ہوتا ہے مگر جب تک دم میں دم ہے ماننا نہیں.دوسرے نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے(سیرۃ النبی لابن ہشام شہادۃ صفیۃ).پس جب کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ ماننا نہیں تو سب دلائل بے کار ہو جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے کس طرح ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں.ہم نے تو انسان کو آزاد بنایا ہے اور ہم نے اُسے کامل مقدرت اور اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ قبول کرے اور چاہے تو ردّ کر دے.اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا.ایسے لوگوں کی موجودگی میں ہم تجھے کس طرح ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں.وَ لَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ اور (یاد رکھ کہ) جب تک تو ان کے دین کی پیروی نہ کرے.یہودی تجھ سے ہر گز خوش نہ ہوں گے اور نہ ہی مسیحی مِلَّتَهُمْ١ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى١ؕ وَ لَىِٕنِ (خوش ہونگے) تُو (ان سے) کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی یقیناً اصل ہدایت ہے.اور اگر تو (اے مخاطب) اس اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ١ۙ مَا علم کے بعد (بھی) جو تیرے پاس آچکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو اللہ (کی طرف ) سے لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ۰۰۱۲۱ نہ کوئی تیرا دوست ہوگا اور نہ مدد گار.حَلّ لُغَات.ھَوٰی محاورہ میں ایسی خواہش کے معنوں میں آتا ہے جو گِری ہوئی ہوتی ہے.اصل میں ھَوْء گڑھے یا قعر کی چیز پر دلالت کرتا ہے.(اقرب) اس لئے یہ لفظ گِری ہوئی خواہش کے لئے استعمال ہوتا ہے.اس میں بتایا ہے کہ اُن کی یہ خواہش نیچے کی طرف لے جانے والی ہے.قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اصلی اور حقیقی معنے بھی الفاظ میں مدِّنظر رکھتا ہے.
Page 431
وَ لِیٌّ جو کسی کے کاموں کو چلائے.محاورہ میں اس کے معنے دوست کے ہیں جو ذمہ دار ہو جائے.اور وَلَایَۃٌ کے معنے حکومت کے بھی ہوتے ہیں پس وَلِیٌّ وہ ہے جو ایجنٹ اور وکیل اور ذمہ دار ہو.(المنجد) نَصِیْرٌ مدد گار کے معنے دیتا ہے اس میں آدمی کام تو خود کرتا ہے مگر دوسرا اُسے سہارا دیتا ہے اور اُس کے لئے سہولت پیدا کرتاہے.مدد دو طرح کی ہوتی ہے اول یہ کہ انسان کلی طور پر دوسرے کا بوجھ اُٹھالے.دوم جزئی طور پر بوجھ اُٹھالے.تفسیر.اِس آیت میں اختلاف کی اصل وجہ بتلائی کہ یہود اور نصاریٰ تم سے اُس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اُن کی بات نہ مان لو اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے خود صداقت کی طرف ہدایت دی ہے پھر جب کہ یہ لوگ صرف رسمی ایمان رکھتے ہیں اور اُن کے ایمان کی بناء نسلی تعصبات پر ہے نہ کہ دلائل و براہین پر.اور باوجود صداقت پیش کرنے کے یہ لوگ اُسے قبول نہیں کرتے.تو جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یا فتہ ہے وہ مشاہدہ کے بعد صداقت کو کب چھوڑ سکتا ہے.قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى.تو اُن کو کہہ دے کہ ان رسمی ایمانوں کو ترک کرو اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ثابت ہو جائے اُسے قبول کرو.کہ اصل ہدایت وہی ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ورنہ اپنی طرف سے ہدایت کے ذرائع تجویز کرنا اور اُن سے نجات کو وابستہ کرنا جُھوٹ ہے.نجات کے قابل صرف وہی شخص ہوتا ہے جو اس ہدایت کو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے مان لے اور اُس پر چلے.وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ میں گو مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن مراد آپ کی جماعت کے لوگ ہیں.اور یہ قرآن کریم کا ایک عام اسلوبِ بیان ہے ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اس بات سے بہت بالا و ارفع ہیں کہ آپؐ کی نسبت یہ کہا جائے کہ شاید آپ ؐ بھی خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپؐ کی نسبت واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (اٰل عمران:۳۲)یعنی اے رسول! تُو لوگوں سے یہ کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو.اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا.اسی طرح فرماتا ہے.لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ اُسْوَۃٌ حَسَنَۃٌ (الاحزاب :۲۲) یقیناً تمہارے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نیک نمونہ پایا جاتا ہے.اگر تم نیک اور پاک بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو.پس اس جگہ آپؐ سے نہیں بلکہ اُمت سے خطاب کیا گیا ہے.اور ھَویٰ کا لفظ رکھ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بُری خواہشات انسان کو ادنیٰ حالت کی طرف لے
Page 432
جاتی ہیں اور اعلیٰ خواہشات دینی ترقی کی طرف لے جاتی ہیں.فرماتا ہے اگر انسان بُری خواہشوں کو قبول کرے تو وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے مقام کو کھو بیٹھتا ہے اگر کوئی اندھیرے میں گِر پڑے اور ٹھوکر کھائے تو وہ درگذر کے قابل سمجھا جاسکتا ہے.لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گِر پڑے تو وہ قابل معافی نہیں ہو سکتا.جس شخص کو دھوکا لگا ہوا ہو اور وہ غلطی میں پڑا ہوا ہووہ قابلِ عفو ہو سکتا ہے لیکن جس شخص پر سچائی کھل جائے اور وہ پھر بھی نہ مانے تو وہ قابلِ عفو نہیں ہو سکتا.مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍمیں فرمایا کہ نہ کلی طور پر کوئی بوجھ اٹھانے والا ملے گا اور نہ جزئی طور پر.اور مِنَ اللّٰہِ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو ہی مدد مل سکتی ہے جو ہوا و ہوس کی پیروی کرنے والا نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ہو.اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ١ؕ اُولٰٓىِٕكَ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی (اسی طرح)پیروی کرتے ہیںجس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے.يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ١ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَؒ۰۰۱۲۲ وہ لوگ اس پر پختہ ایمان رکھتے ہیں.اور جو لوگ اس کا انکار کریںوہی نقصان اٹھانے والے ہیں.حَلّ لُغَات.تِلَاوَتِہٖ : تَلَا یَتْلُوْ کے معنے پڑھنے کے ہیں.پس یَتْلُوْ نَہٗ حَقَّ تِلَا وَتِہٖ کے معنے یہ ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے یا جس غور و فکر سے اس کو پڑھنا چاہیے اسی غورو فکر سے اُسے پڑھتے ہیں.(۲) تَـلَا کے معنے پیچھے چلنے کے بھی ہیں.یعنی کہنے کے مطابق عمل کرنا.پس يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ کے یہ بھی معنے ہیں کہ یَتَّبِعُوْنَہٗ حَقَّ اِتِّبَاعِہٖ (اقرب).جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اُس پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں.ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے.فرماتا ہے.وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلٰىهَا(الشمس :۳) کہ ہم چاند کو بطور شہادت کے پیش کرتے ہیںجبکہ وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے.اس صورت میں حَقَّ تِلَاوَتِہٖ حال ہے.دوسری صورت میں یہ خبر بنتا ہے حال نہیں رہتا.یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اُن کی خبر یہ ہے کہ وہ اس پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں.
Page 433
تفسیر.اس جگہ لوگوں نے غلطی سے اَلْکِتٰب سے مراد بائیبل لی ہے.مگر یہ معنے اس جگہ کسی طرح چسپاں نہیں ہوسکتے.کیونکہ اگر اس سے بائیبل مراد لیں تو اس صورت میں آیت کاترجمہ یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے بائیبل دی ہے وہ اس کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جس طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے اور وہ اس کی صداقت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں حالانکہ نہ یہودی تورات پر عمل کررہے تھے اور نہ عیسائی انجیل پر عمل کرتے تھے.پس یہ معنے یہاں چسپاں ہی نہیں ہو سکتے.یہاں اَلْکِتٰب سے مراد وہی کتاب ہو سکتی ہے جس کے ماننے والے اس کی کامل پیروی کرتے تھے.جب بائیبل کے احکام پر عمل ہی نہیں کیا جاتا تھا تو اَلْکِتٰب سے تورا ت کس طرح مراد ہو سکتی ہے.پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ٖوسلم کے زمانہ میں تورات و انجیل سب محرف و مبدل ہو چکی تھیں.اور اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہی تھیں جیسا کہ وہ یہود کے متعلق فرماتا ہے کہ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ١ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (البقرۃ :۸۰) یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے تورات میں بعض باتیں بڑھا دیتے اور پھر کہہ دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ الہام ہے.اتنی بڑی تحریف کے بعد اُن کی خوبیاں بیان کرنے اور تعریف کرنے کے کوئی معنے ہی نہیں ہو سکتے تھے.اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن کریم کی کوئی ضرورت نہ تھی.تورات اور انجیل ہی لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھیں.پس یہاں اَلْکِتٰب سے مراد قرآن کریم ہے نہ کہ تورات.چونکہ دوسری جگہ یہود کے لئے بھی اہل کتاب کا لفظ آیا ہے اس لئے لوگ غلطی سے یہاں بھی وہی مراد لے لیتے ہیں.حالانکہ ہمیشہ قرائن کو مدِّنظر رکھ کر معنے کرنے چاہئیں.اگر کوئی غیر مشترک لفظ ہو تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا.لیکن مشترک لفظ ہو تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ قرینہ دیکھا جاتا ہے اور یہ بھی کہ آیت کے معنے کس فریق پر چسپاں ہو سکتے ہیں چونکہ اَلْکِتٰب کا لفظ تورات پر بھی بولا جاتا ہے اور قرآن کریم پر بھی اس لئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس جگہ اَلْکِتٰب کا لفظ کس کے متعلق استعمال کیا گیا ہے.حضرت قتادہؓ جو رئیس التابعین ہیں اُن کا قول ہے کہ اس جگہ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ سے مسلمان مراد ہیں اور اَلْکِتٰب سے مراد قرآن کریم ہے (ابنِ کثیرزیر آیت ھٰذا) درحقیقت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو ملزم قرار دیا ہے کہ تم نے تو تورات کو پسِ پشت پھینک رکھا تھا مگر اب یہ لوگ جن کو ہم نے قرآن کریم دیا ہے اس پر پوری طرح عمل کرتے ہیں.اور خدا تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لئے اُس کے ایک ایک حکم کو بجا لاتے ہیں.تم کہتے تھے کہ ہمارے پاس سچی کتاب ہے حالانکہ اگرتمہارے پاس سچی کتاب ہوتی تو چاہیے تھا کہ تم اس پر عمل بھی کرتے اور تم ہدایت یافتہ وجود ہوتے.مگر تم خود بھی تسلیم کرتے ہو کہ ہم خراب ہو گئے ہیں اس لئے لازماً اب کوئی ایسی قوم ہونی چاہیے تھی جو اپنا مال،اپنا آرام اور اپنی جانیں قربان کرتی اور خدا تعالیٰ کے
Page 434
دین کو ازسرِ نو قائم کرتی اور چونکہ یہ لوگ اپنا مال، اپناآرام اور اپنی جانیں اسلام کے لئے قربان کر رہے ہیں اس لئے معلوم ہوا کہ یہی لوگ حق پر ہیں اور جس کتاب پر ایمان لائے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ جو کتاب دنیا میں ہدایت قائم کر دیتی ہے وہی خدا کی طرف سے نازل شدہ سمجھی جاسکتی ہے.اُولٰٓىِٕكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ یہ دوسرا جملہ ہے یعنی وہی اس پر پختہ ایمان لاتے ہیں.یہ اس رسمی ایمان کے علاوہ ہے جس کا پہلے ذکر آچکا ہے.دراصل ایمان کے دو۲ مدارج ہیں پہلا درجہ دلیل کے ساتھ ایمان لانا ہے مگر دلیل انسان کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جسے مشاہدہ کا مقام کہتے ہیں.وہ ماننا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بادشاہ یا حاکم وقت کی حکومت مان لی جائے.مگر دوسرا درجہ انکشاف کا ہوتا ہے.اس مقام پر پہنچ کر انسان کا خدا تعالیٰ سے اتصال ہو جاتا ہے اور رسمی ایمان حقیقی ایمان کی شکل اختیار کر کے اس کا جزوبن جاتا ہے اور اُسے بشاشت قلبی حاصل ہو جاتی ہے.جس کے بعد اُس کے لئے کسی ارتداد یا ٹھوکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ اَلْکِتٰب سے یہاں قرآن کریم ہی مراد ہے نہ کہ بائیبل.کیونکہ قرآن کریم کی موجودگی میں بائیبل کا انکار کرنے والے خاسر نہ تھے بلکہ بائیبل پر عمل کرنیوالے خاسر تھے.صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس پر ایمان نہ لا کر انسان خسارہ پاتا ہے لیکن باقی کتابوں کو چھوڑ کر انسان خسارہ نہیں بلکہ نفع پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے اس رکو ع کی آیت۱۱۴ میں یہودو نصاریٰ کی ایک اور بدی بیان فرمائی تھی کہ یہ ایک دوسرے کو ازراہ تعصب و ضِد بُرا کہتے ہیں اور ان کی کسی خوبی کے بھی قائل نہیں حالانکہ ایک کتاب کو ماننے کی وجہ سے ان میں کچھ باتیں مشترک بھی ہیں.آیت نمبر۱۱۵ میں بتایا کہ اُن کا بُغض اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو عبادت کرتے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے.مقدس مقامات میں گھسنے نہیں دیتے حالانکہ عبادت خانوں کے معاملہ میں نہایت خوف سے کام لینا چاہیے.آیت۱۱۶ میں مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی مخالفت سے مت ڈرو.یہ موردِ غضب الہٰی ہو رہے ہیں.جدھر تمہاری توجہ ہو گی اُدھر ہی اللہ تعالیٰ تمہاری کامیابی کے سامان پیدا کر ے گا.آیت۱۱۷ میں یہودی مذہب کی شاخ مسیحیت کی بُرائی بھی بتا دی تاکہ اُن کو بھی معلوم ہو جائے کہ اُن میں نبی کیوں پیدا نہ ہوا اور کیوں وہ مکالمہ و مخاطبہ الٰہیہ کی نعمت سے محروم ہیں.آیت۱۱۸ میں ابنیت کے غلط مفہوم کی تین دلائل سے تردید فرمائی.آیت۱۱۹ میں اُن کے دو۲ اعتراضوں کے جواب دیئے.اول اس کا کہ اگر ہم غلطی پر ہیں تو خدا تعالیٰ بذریعہ الہام ہمیں کیوں آگاہ نہیں کرتا.دوم ہم پر باوجود مخالفت کے عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا.آیت۱۲۰ میں بتایا کہ ہر رسول بشیر اور نذیر ہوتا ہے.پس عذاب تو ضرور آئے گا مگر آہستہ آہستہ.
Page 435
آیت۱۲۱ میں مخالفت کی اصل وجہ بتائی کہ اُن کی خواہشات کے مطابق تمہاری تعلیم نہیں.اس کا جواب یہ دیا کہ صراطِ مستقیم وہی ہے جس پر خدا تعالیٰ قائم کرے پس جو ہدایت کو دیکھ کر پھر گمراہی کی طرف جھکے گا وہ سزا پائے گا.آیت۱۲۲ میں فرمایا کہ مسلمان جن کو ہم نے قرآن کریم عطا کیا ہے اور جو اس کی تعلیم پر کامل طور پر عمل پیرا ہیں وہ ایک دن کامیاب ہوں گے اور خسارہ پانے والے صرف وہی لوگ ہوں گےجو اس کتاب کے منکر ہیں.يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اے بنی اسرائیل ! میرے اس احسان کو جو مَیں تم پر کر چکا ہوں یاد کرو وَ اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۰۰۱۲۳ اور (اس بات کو بھی ) کہ مَیں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی.تفسیر.وہ مضمون جو گذشتہ رکوع پر ختم کیا گیا ہے پانچویں رکوع سے شروع ہوا تھا.حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ کلامِ الٰہی کا نزول ابتدائے انسانیت سے جاری ہے بنی اسرائیل کے انعامات کا ذکر کیا گیا تھااور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِيْۤ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ١ۚ وَ اِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ (البقرۃ :۴۱) یعنی اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ہی ڈرو.اس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت شروع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح ؑ ناصری کے زمانہ تک پہنچی.پس جب وہ تمہارے قریب ترین زمانہ تک چلی آئی ہے اور اس میں کوئی انقطاع واقع نہیں ہوا تو کوئی وجہ نہیں کہ جو سلسلہ ابتدائے عالم سے چلا آرہا ہے اسے اب تم ختم سمجھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کردو.قرآن کریم کا طریق ہے کہ جب وہ کسی مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہاں کوئی قرینہ رکھ دیتا ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب نیا مضمون شروع ہونے والا ہے.اس جگہ بھیيٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل ان تمام باتوں کے بعد جو ہم نے تمہارے سامنے بیان کی ہیں تم یاد تو کرو کہ مَیں نے اپنی نعمت تم پر کس طرح مکمل کی اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ مَیںنے تم کو تمام قوموں پر فضیلت دی یعنی دو قسم کی برکات تم پر نازل ہوئیں ایک تو یہ کہ نعمت نبوت
Page 436
تمہیں عطا ہوئی اور دوسرے وہ نعمت ایسی تھی جس نے تمام قوموں پر تمہیں فضیلت دے دی تھی.اس جگہ بنی اسرائیل کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے متواتر انعامات یاد دلا کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ بنی اسرائیل کو اب شکایت کا کوئی حق نہیں کہ نعمت ِ نبوت بنو اسمٰعیل کو کیوں عطا کی گئی ہے کیونکہ ان سے وعدہ پورا ہو چکا ہے.اب جس خدا نے ان کا وعدہ پورا کیا ضروری تھا کہ وہ بنو اسمٰعیل کا وعدہ بھی پورا کرتا.کیونکہ حضرت ابراہیم ؑ سے خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اُن کے دونوںبیٹوں کے ساتھ نیک سلوک کروںگا(پیدائش باب ۱۵ و ۱۷) جب ایک سے وعدہ پورا ہوا تو ضروری تھا کہ دوسرے سے بھی پورا ہو.پس اب اُن کے لئے کسی شکایت کا موقع نہیں.اَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.یہ قرآن کریم کا محاورہ ہے کہ جس قوم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی آئے اور اُسے کلامِ الہٰی کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے اُس کے لئے فَضَّلْتُكُمْکے الفاظ آتے ہیں.کیونکہ الہام کو باقی علوم پر فضیلت حاصل ہوتی ہے.باقی علوم میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں.مگر الہام میں کوئی غلطی نہیں ہوتی.اس لئے جو قوم موردِ الہامِ الہٰی ہو وہ تمام قوموں پر فضیلت رکھتی ہے.اس میں عَالَمِیْن سے تمام دنیا کی قومیں مراد نہیں.بلکہ صرف وہ قومیں مراد ہیں جن میں الہام الہٰی کا سلسلہ جاری نہیں تھا.کیونکہ اس جگہ صرف وحیٔ نبوت کو فضیلت کا موجب قرار دیا گیا ہے پس وحی الہٰی کی مورد اقوام اس میں شامل نہیں بلکہ صرف غیر وحی والی اقوام عَالَمِیْن میں شامل ہیں.اس لئے یہ جھگڑا ہی غلط ہے کہ اس قوم کو اس پر فضیلت ہے اور اس کو اُس پر فضیلت ہے کیونکہ یہ الفاظ قرآن کریم میں مختلف اقوام کے متعلق استعمال ہوئے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرآن کریم کا یہ ہرگز منشا نہیں کہ وہ تمام قومیں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتی ہیں مثلاً سورۃ آل عمران میں آتا ہے.اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (آل عمران:۳۴)یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم ؑ اور نوح ؑ اور آلِ ابراہیم ؑ اور آلِ عمران کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی.اب اس میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تمام عالموں پر فضیلت دی تھی اور آل ابراہیم ؑ اور آل عمران کو بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی حالانکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام بنی آدم پر فضیلت تھی توپھر حضر ت نوح علیہ السلام کو تمام پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ آدم ؑ اُن کے دائرہ سے نکل گئے.اور اگر حضرت نوح علیہ السلام کو باہر نکال لیں تو آدم علیہ السلام کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی.اسی طرح آلِ ابراہیم ؑ کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے اُسے بھی تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی.اب اگر بنو اسمٰعیل کو سب پر فضیلت ہو تو بنو اسحاق کونہیں ہو سکتی اور اگر بنو اسحاق کو سب پر فضیلت ہو تو بنو اسمٰعیل ؑ کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل کو سب پر فضیلت ہو تو آل ابراہیم ؑ کو سب پر فضیلت
Page 437
نہیں ہو سکتی اور اگر آلِ عمران کو سب پر فضیلت حاصل ہو تو آلِ ابراہیم ؑ کو سب پر فضیلت نہیں ہو سکتی.پس اس آیت کے یا تو یہ معنے ہیں کہ اُن سب کو اپنے اپنے زمانہ میں باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل تھی اور یا پھر یہ معنے ہیں کہ صاحبِ وحی کو غیر صاحبِ وحی پر فضیلت ہو تی ہے.وحی کا تو صرف ایک عالم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک ہی ہے لیکن کفر کے کئی عالم ہوتے ہیں.ان عالموں کے افراد نزولِ وحی کو بھول کر باطل باتیں اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی نبی کی طرف نہیں بلکہ کسی فلسفی کی طرف منسوب کر نے لگ جاتے ہیں.جیسے بہت سے عیسائی اپنے آپ کو فلسفہ کا تابع قرار دیتے ہیں.مسلمان بھی آہستہ آہستہ یونانی فلسفہ کی طرف مائل ہو گئے تھے.اور گو کوئی قوم ایسی نہیں جس کی بناء کسی مذہب کے ہاتھوں نہ رکھی گئی ہو لیکن افراد کے لحاظ سے کروڑوں ایسے ہیں جو کسی کتاب کے تابع نہیں ہیں.اسی طرح الہام کی اتباع کا دعویٰ کرنے کے باوجود ہزاروں مسلمان ایسے ہیں جو مذہب سے بیگانہ ہیں اور فلسفہ کے قائل ہیں.غرض تمام علمی اور اخلاقی اور اعتقادی باتوں پر الہام کو ہمیشہ فضیلت حاصل رہی ہے.فلسفیوں کی باتیں کمزور اور ناقص نظر آئیں گی اور الہام الہٰی کی باتیں مضبوط اور غالب دکھائی دیںگی.پس فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تشریح کی ہے اور بتایا ہے کہ اس نعمت سے مراد انبیاء اور رُسُل کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو بنی اسرائیل میں جاری رہا جیسا کہ قرآن کریم میں سورۃ فاتحہ میں ایک طرف تو مومنوں کو یہ دُعا سکھلائی کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ اور دوسری طرف منعم علیہ گروہ کی تعیین کرتے ہوئے فرمایا کہ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ۠ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ(النّساء :۷۰) یعنی جو لوگ اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کریںگے وہ اُن لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا.یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین.پس چونکہ کمالِ انعام وحی سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم پر وحی نازل کر کے تمہیں غیر وحی والی قوموں پر بڑی بھاری فضیلت دی تھی اور جس طرح یہ کمال تمہیں صرف وحی کی وجہ سے حاصل ہوا تھا اسی طرح اب مسلمانوں کو تم پر وحی کے ذریعہ فضیلت دے دی گئی ہے.اگر تم اسے ردّ کرو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہو گا جو تمہارے مقابل پر دوسروں کاہوا تھا.بنی اسرائیل تجربہ کر چکے تھے کہ بڑے بڑے فلاسفر موسیٰ ؑ کے الہام کے مقابلہ پر آئے مگر ان تمام کو تورات نے شکست دی.پس فرمایا کہ اگر تم اس کے مقابلہ پرآئو گے تو تمہاری عقلیں بھی کسی کام نہ آئیں گی اور تم اس کے مقابلہ میں ناکام رہو گے.
Page 438
وَ اتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّ لَا يُقْبَلُ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص قطعاً کسی دوسرے شخص کا قائم مقام نہ ہو سکے گااور نہ اس سے کسی قسم کا مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ۰۰۱۲۴ معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی.تفسیر.یہ آیت سورۃ بقرۃ کے رکوع۶ میں بھی آچکی ہے مگر اس فرق کے ساتھ کہ اُس آیت میں لَایُقْبَلُ مِنْھَا شَفَاعَۃٌ تھا اور اس میں لَایُقْبَلُ مِنْھَا عَدْلٌہے پھر پہلی آیت میں جہاں وَلَا یُوْ خَذُ مِنْھَا عَدْلٌ تھا وہاں اس آیت میں وَلَا تَنْفَعُھَا شَفَاعَۃٌ(البقرۃ:۴۹)رکھ دیا.اسی طرح پہلی آیت میںعدل کا ذکر تیسری جگہ تھا اور شفاعت کا دوسری جگہ اور اس میں شفاعت کا تیسری جگہ اور عدل کا دوسری جگہ ذکر ہے.گویا اِن دو آیات میں تین فرق ہیں.(۱)ایک فرق تویہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کا ذکر پہلے تھا اور عدل کا بعد میں لیکن دوسری آیت میں عدل کا ذکر دوسری جگہ آگیا ہے اور شفاعت کا ذکر تیسری جگہ.(۲) دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں عدل کے متعلق لَا یُؤْ خَذُ کے الفاظ تھے اور دوسری آیت میں لَا یُقْبَلُ آگیاہے.(۳) تیسرا فرق یہ ہے کہ پہلی آیت میں شفاعت کے لئے لَایُقْبَلُ تھا اور دوسری آیت میں لَاتَنْفَعُھَا کر دیا گیا.اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت اس مقام پر بیان کی گئی ہے جبکہ ابھی بنی اسرائیل کے عیوب شمار نہیں کئے گئے تھے.اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب تک انسان پر اپنی کمزوریاں نہیں کھلتیں اُس کی اُمیدیں وسیع ہوتی ہیںاور وہ اپنے بزرگوں کی امداد پر زیادہ بھروسہ رکھتا ہے.اس لئے پہلی آیت میں شفاعت کو پہلے رکھا گیا ہے.کیونکہ یہود یہ اُمید رکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری شفاعت کر کے ہمیں بچالیں گے اور وَلَا یُؤْخَذُ مِنْھَا عَدْ لٌ کو بعد میں رکھا گیا.کیونکہ جسے شفاعت کی اُمید ہو وہ عدل دینے پر زیادہ آمادہ نہیں ہوتاکیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بغیر اس کے بھی کام نکل جائے گا.لیکن اس آیت کے بعد جب یہود کی نافرمانیاں اور انبیاء کی مخالفتیں چھٹے رکوع سے شروع کر کے پندرھویں رکوع تک بیان کر دی گئیں اور ان کی مخالفتِ انبیاء کا راز فاش کر دیا گیا تو ان کی یہ اُمید بھی جاتی رہی کہ نبی ہماری شفاعت کرینگے.اس لئے اب طبعی ترتیب یہ ہو گی کہ عدل کا ذکر پہلے ہو اور شفاعت کا ذکر بعد میں کیونکہ اب وہ شفاعت پر زیادہ زور نہیں دے سکتے تھے اور اُن کی یہ امید کمزور ہو گئی تھی صرف عدل ہی رہ گیا تھا کہ شاید بدلہ دے کر چھوٹ جائیں اس لئے پہلے
Page 440
حقیقت یہ ہے کہ جب قومیں اپنے تنزل کے دور میں اعمال صالحہ کی بجا آوری میں کمزور ہو جاتی ہیں تو وہ شفاعتِ انبیاء پر زور دینے لگ جاتی ہیں.صحابہؓ کے اقوال میں ہمیں یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم نجات حاصل کرلیں گے.بلکہ اُن کے کلام میں نیکی اور تقویٰ اور قرآن کریم پر عمل اور قربانیاں کرنے پر خاص طور پر زور پایاجاتا ہے مگر جُوں جُوں انبیاء سے بُعد ہوتا جاتا ہے لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کی شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے.چونکہ یہود بھی شفاعتِ انبیاء پر بھروسہ کر کے بیٹھے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا اس آیت میں ردّ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کا یہ خیال اُن کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیگا.جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس لئے ابراہیم ؑ ہماری شفاعت کریں گے یا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اس لئے موسیٰ ؑ ہماری شفاعت کرینگے وہ غلطی پر ہیں.جب اس مضمون کو رکوع ۶ سے شروع کیا گیا تھا تو اس وقت چونکہ یہود کے اس دعوے کو ردّ کرنے پر خاص طور پر زور دینا مدّنظر تھا کہ انبیاء ہماری شفاعت کریں گے اس لئے شفاعت کو جس پر سارازور تھا مقدّم رکھا.اور فرمایا کہ ان کے متعلق نہ شفاعت قبول کی جائے گی جسے یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اور نہ یہ اپنے بد اعمال کا معاوضہ پیش کر سکیں گے.لَایُقْبَلُ مِنْھَا شَفَاعَۃٌ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شرمندہ کیا ہے کہ تم کس مُنہ سے کہتے ہو کہ انبیاء ہماری شفاعت کرینگے کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تھی.کیا سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کی تھی کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی تھی.کیا دوسرے انبیاء کی اطاعت کی تھی تم نے ہر ایک کا انکار کیا اور اس کی مخالفت کی.اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں.اس لئے ہم اس پر کس طرح ایمان لائیں.حالانکہ سوال یہ ہے کہ تم نے کس نبی کی مخالفت نہیں کی؟ تم ہر ایک سے لڑتے رہے اور تم نے ہر ایک کی تکذیب کی پس جب ہر ایک کی تم تکذیب ہی کرتے رہے ہو تو اب تمہاری کون شفاعت کریگا.کیا موسیٰ علیہ السلام کریں گے جن کو تم نے فَاذْھَبْ اَنْتَ وَرَبُّکَ فَقَاتِلَٓا اِنَّا ھٰھُنَا قَاعِدُوْنَ (المائدة:۲۵) کہا تھا یا حضرت سلیمان علیہ السلام کریں گے جن کو تم نے کافر قرار دیا تھا.یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرینگے جن کو تم نے لعنتی قرار دیا تھا.آخر تم کس کی شفاعت کے امیدوار ہو.اس کے بعد چونکہ شفاعت پر اُن کو زیادہ گھمنڈ نہیں ہوسکتا تھا اور اُن کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں اس لئے اب قدرتی طور پر انہیں یہی خیال ہو سکتا تھا کہ کوئی بدلہ لے کر چھوڑ دے.اس وجہ سے مضمون بھی تبدیل کر دیا گیا اور عدل کو پہلے اور شفاعت کو بعد میں رکھ دیا گیا اور مایوسی کے کمال کو ظاہر کرنے کے لئے یُؤْخَذُ
Page 441
کے بجاے عدل کے ساتھ یُقْبَلُ کا لفظ رکھا گیا.یعنی وہ تو چاہیں گے کہ بدلہ لے لیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا.اسی طرح شفاعت کے ساتھ لَاتَنْفَعُھَا کے الفاظ رکھ دیئے کہ شفاعت کرنے والے دوسروں کی تو شفاعت کریںگے مگر ان کے حق میں انہیں اِذْن ہی نہیں دیا جائے گا.کہ شفاعت اُن کو فائدہ دے سکے گویا نہ ان کے اعمال اُن کے کام آئیں گے اور نہ شفاعت ان کو کوئی نفع دےگی.شفاعت کی قبولیت درحقیقت کلّی طور پر ہوتی ہے اگر شفاعت قبول ہو جائے تو انسان جنت میں چلا جاتا ہے لیکن اعمال صرف جزئی طور پر فائدہ دے سکتے ہیں یعنی جتنے عمل اچھے ہوں اتنے کام آسکتے ہیں پس فرمایا کہ ان کو قلیل طور پر بھی نفع نہیں ہو سکتا اور نہ شفاعت کے ذریعہ کلّی طور پر نفع ہو سکتا ہے.تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے.اس کے لئے فرما دیا کہ وَلَا ھُمْ یُنْصَرُوْنَ.اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں کوئی مدد نہیں دی جائیگی.غرض تین ہی صورتیں ہو سکتی تھیں اور تینوں کی نفی کر دی گئی ہے یعنی نہ تو ان کے حق میں شفاعت ِ انبیاء ہو گی اور نہ ان کے اعمال اُن کے کام آئیں گے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی مدد حاصل ہو گی.صرف یہی صورت ان کی نجات کی تھی کہ اوّل اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کر کے انہیں معاف کر دے.دوم انبیاء اُن کی شفاعت کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیں.سوم ان کے اپنے اعمال انکے کام آجائیں اور وہ انکو اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بنا دیں.مگر اُن کے لئے یہ تینوں راستے بند کر دیئے گئے ہیں.نہ ان کی شفاعت ہوگی نہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ انہیں بچا سکیں اور نہ ہم مدد دیںگے.وَ اِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ١ؕ قَالَ اِنِّيْ اور( اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ابراہیم ؑ کو اس کے رب نے بعض باتوں کے ذریعہ سے آزمایا اور اس نے ان کو پورا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا١ؕ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ١ؕ قَالَ کردکھایا (اس پر اللہ نے ) فرمایا کہ میں تجھے یقیناً لوگوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں (ابراہیم ؑ نے) کہا اور میری لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ۰۰۱۲۵ اولادسے بھی (امام بنا ئیو) (اللہ نے ) فرمایا (ہاں! مگر) میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا.حَلّ لُغَات.اِبْتَلٰی کے دو معنے ہیں.اوّل کسی کی مخفی باتوں کو معلوم کرنا.دوم کسی کی پوشیدہ قابلیتوں کو
Page 442
خواہ وہ نیک ہوں یا بد اچھی ہوں یا بُری ظاہر کرنا.جب اس لفظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور کہا جائے.اِبْتَلَی اللّٰہُ فُلَانًا تو اس سے دوسرے معنے مراد ہوتے ہیں.یعنی کسی کی پوشیدہ قابلیتوں کو ظاہر کردیا.کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے اُسے خود کوئی بات معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.(مفردات) کَلِمَۃٌ کے معنے حکم کے ہوتے ہیں اور حکم میں اوامرونواہی دونوں شامل ہیں.(مفردات راغب) اَ لْاِمَامُ کے معنے ہیں اَلْمُؤْ تَمُّ بِہٖ جسے اُسوہ بنایا جائے.اور جس کے قول و فعل کی اقتداء کی جائے.(۲)عربی زبان میں کتاب کو بھی امام کہتے ہیں.(مفردات)کیونکہ اس کے احکام کو مانا جاتا ہے.تفسیر.فرماتا ہے تم اُس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اندرونی نیکی اور تقویٰ کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہا.تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخفی رُوحانی طاقتیں اور قابلیتیں اُن کو معلوم ہو جائیں چنانچہ ان قابلیتوں کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کو کچھ احکام دیئے.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام کو پورا کر دیا.اور اس طرح دُنیا کو معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اطاعت اور فرمانبرداری کی جو اعلیٰ طاقتیں و دیعت ہیں وہ دوسروں میں نہیں ہیں.مثلاً اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیں.جب وہ ظاہری طور پر اس پر عمل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری یہ مراد نہیں بلکہ کچھ اور مراد ہے.اور پھر اللہ تعالیٰ کا منشاء اس رنگ میں ظاہر ہوا کہ اُس نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہاجرہ اور اسمٰعیل کو ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آئیں.چنانچہ وہ انہیں وہاں چھوڑ آئے اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح دنیا کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہر بات پر لبّیک کہنے والے ہیں.خواہ بادی النظر میں وہ کتنی ہی بھیانک اور خوفناک کیوںنہ ہو.یہاں وَاِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰھٖمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ فرمایا ہے اور کَلِمٰتٍ جمع کا صیغہ ہے مگر مشہور اُن کے بیٹے کے ذبح کا واقعہ ہے لیکن طالمود میں لکھا ہے کہ اُن کی دس ۱۰ آزمائشیں ہوئی تھیں.(جوزف بارسلے کی طالمود صفحہ۱۰۸) اِنِّیْ جَا عِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَا مًا میں امامت سے نبوت مراد نہیں کیونکہ نبوت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی.اس جگہ امامت سے انہیں لوگوں کے لئے ایک نمونہ اور مقتدیٰ بنانا مراد ہے اور لِلنَّاسِ سے مراد انسانوں کا عظیم الشان گروہ ہے.درحقیقت اِس میں آئندہ کے متعلق ایک وعدہ کیا گیا تھا.ورنہ اُس زمانہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف چند ہی لوگ تھے.چنانچہ دیکھ لو آج دنیا کے کثیر حصہ میں وہ امام اور مقتدیٰ سمجھے جاتے ہیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے.یوں تو ہر نبی اپنی قوم کے لئے اُسوہ ہوتا
Page 443
ہے لیکن ہر نبی ساری دنیا کے لئے اُسوہ نہیں ہوتا.انبیاء سابقین میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تمام اقوام میں ادب اور احترام پایا جاتا ہے.عیسائیوں کو ہی دیکھ لو.وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا حضر ت ابراہیم علیہ السلام کا کرتے ہیں بلکہ دوسرے نبیوں پر تو وہ کئی قسم کے الزام بھی لگاتے ہیں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ خاص طور پر ادب کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے مانتے ہیں.ورنہ باقی انبیاء کو تو وہ چور اور بٹمار کہنے سے بھی باز نہیں آتے(یوحنا باب۱۰آیت۸) مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ادب کرتے ہیں یہی معنے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کے ہیں یعنی ہم تجھے ایک ایسا وجود بنائیں گے کہ لوگ تیرے اقوال و افعال کی اقتداء کرینگے.چنانچہ حج جو اسلامی عبادات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے.انہوں نے ہی قائم کیا اور آج تک دنیا حج کے ذریعے ان کو یاد کرتی ہے.اسی طرح ہر قربانی کے موقعہ پر وہ یاد کئے جاتے ہیں.ہم اگرچہ اُمتِ محمدیہؐ میں سے ہیں مگر ہم بھی عیدالاضحیہ کے موقعہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اسلام میں کوئی دن مقرر نہیں کیا گیا کہ جس سے اُن کے کسی فعل کی یاد تازہ ہو.لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے لئے ایک خاص دن مقرر کر دیا گیا ہے.پس امامت سے مراد نبوت نہیں بلکہ اُن کا اُسوہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے تمام لوگوں کے لئے ایک نمونہ بنائیںگے اور لوگ تیری اقتداء کرتے رہیں گے.شیعہ دوست کہا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ایسے وقت میں فرمایا ہے جبکہ آپ نبی بن چکے تھے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کا مقام نبی سے بالا ہوتا ہے.اُن کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت نبوت کے دعویٰ کے بعد دی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام اپنے لغوی معنوں کے لحاظ سے کوئی ایسا عہدہ ہے جو نبوت کے بعد ملتا ہے.اگر یہ ایسا عہدہ ہے جو نبوت کے بعد ملتا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ بعض نبی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اقتداء ضروری نہیں ہوتی کیونکہ لُغت نے امام کے یہ معنے بتائے ہیں جس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے.پس اگر یہ ایسا عہدہ ہے جو نبوت سے فائق ہے تو ماننا پڑے گا کہ بعض نبی ایسے بھی ہوئے ہیں جن کی اطاعت و فرمانبرداری فرض نہیں تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت بھی اس سے پہلے فرض نہ تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَآ اَرْسَلْنَامِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِیُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰہِ (النّساء:۶۵) یعنی ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کی اطاعت دوسروں پر فرض نہ کی گئی ہو.اس سے معلوم ہوتا
Page 444
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اطاعت فرض کی ہوئی ہے.اِدھر وہ نبی بنتا ہے اور اُدھر اُس کی بات کا ماننا واجب ہو جاتا ہے.اِن معنوں کی رُو سے امامت نبوت سے علیٰحدہ کوئی مقام نہ رہا بلکہ امامت و نبوت دونوں لازم و ملزوم قرار پاتی ہیں.پھر ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک امامت نبوت سے بھی پہلے ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اَطِیْعُوا اللّٰہَ وَ اَطِیْعُواالرَّسُوْلَ وَاُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمْ(النّساء:۶۰) یعنی اے مومنو! تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو.اور جو اولی الامر اور غیر رسول ہیں اُن کی بھی اطاعت کرو.پہلے اللہ پھر رسول اور پھر اُن سے نیچے اولی الامر غیر رسول کو رکھا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رسول نہیں ہوتے.مگر اُن کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے.اگر امام کے معنے صرف مطاع کے لئے جائیں تو اِس قسم کی امامت تو نبوت سے بھی ادنیٰ ہوئی.جو امامت نبوت کے ساتھ لازم ہوتی ہے وہ نبوت کے ساتھ ہی حاصل ہو جاتی ہے.یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی تو ہو مگر اُسے امامت نہ ملی ہو.یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص امام ہو مگر اُسے نبوت نہ ملی ہو.مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص نبی اور رسول ہو اور پھر امامت سے محروم ہو.جیسا کہ وَمَااَرْسَلْنَامِنْ رَسُوْلٍ اِلَّا لِیُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰہِ سے ظاہر ہے.اب ہمیںدو۲ باتوں میں سے ایک بات ضرور ماننی پڑتی ہے یا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے یا نبوت کے بعد کی بات ہے اگر نبوت کے بعد کی بات ہے تو اس صورت میں اس کے وہ معنے نہیں ہو سکتے جو عام طور پر کئے جاتے ہیں.بلکہ اس کے کچھ اور معنے ہوں گے.اور واقعہ یہی ہے کہ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا نبوت کے بعد فرمایا گیا ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض کلمات کے ذریعہ آزمائش کی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اُن احکام الٰہی کو پورا کر دیا.اور انبیاء کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے ملنے سے پہلے امتحان نہیں لیاجاتا.بلکہ بعد میں لیا جاتا ہے اس لئے باقی انبیاء کے طریق کو دیکھتے ہوئے ماننا پڑتا ہے کہ یہ الہام بعد کا ہے.اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے کوئی اور معنے ہو سکتے ہیں یا نہیں.سو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر لفظ دو۲ قسم کے معنے رکھتا ہے.اول اضافی دوم غیر اضافی.اضافی معنے ہمیشہ اضافت کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں.مثلاً جب ہم سردار کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے عام طور پر یہ معنے ہوتے ہیں کہ جو کسی کے اوپر افسر ہو.لیکن سردار ایک گائوں کا بھی ہوتا ہے ایک تحصیل کا بھی ہوتا ہے.ایک ضلع کا بھی ہوتا ہے.ایک صوبے کا بھی ہوتا ہے ایک ملک کا بھی ہوتا ہے اور پھر کئی ملکوں کا بھی ہوتا ہے.پس یہ ایک عام لفظ ہے جو چھوٹے بڑے سب کی سرداری پر دلالت کرتا ہے اور کسی کی طرف اضافت کرنے کے بغیر کوئی خاص معنے معیّن نہیں کرتا.مگر جب ہم یہ کہیں کہ چوہڑوں کا سردار یا چپڑاسیوں کا سردار یا جرنیلوں کا سردار تو اس کے معنے معیّن ہو جاتے
Page 445
ہیں.اور پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں قوم سے اسے نسبت ہے اور اس اضافت سے معنوں میں فرق پڑ جاتا ہے.اس کی مثال قرآن کریم میں بھی ملتی ہے.قرآن کریم میں صدّیق کا لفظ آتا ہے جس کے معنے بڑے راستباز کے ہیں اب بڑا راستباز نبی بھی ہوسکتا ہے اور غیر نبی بھی.اگر صدّیق کالفظ عام معنوں میں ہو تو یہ درجہ نبی سے چھوٹا ہے مگر جب یہ لفظ نبی کے لئے آئے تو اس وقت یہ کسی خاص خصوصیت کا حامل بن جاتا ہے.جیسے قرآن کریم میں حضرت ادریس ؑ کے متعلق آتا ہے.وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ١ٞ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (مریم :۵۷) یعنی تو قرآن کریم کی رو سے ادریس ؑ کا بھی ذکر کر وہ ایک صدیق نبی تھا.حالانکہ دوسری جگہ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ۠ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ(النّساء:۷۰)میں صدّیقیت کو نبوت سے نیچے رکھا ہے.اسی طرح حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی نسبت آتا ہے كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا (مریم:۵۶) کہ وہ اپنے رب کے حضور پسندیدہ وجود تھا.مگر دوسری جگہ یہ درجہ نبوت سے نیچے رکھا ہے.جیسے فرمایا.يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ.ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (الفجر :۲۸،۲۹) کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف ایسی حالت میں واپس جا کہ تو اس سے اور وہ تجھ سے راضی ہے.اِس آیت میں ہر مومن کا نام جو نفسِ مطمئنہ رکھتا ہے اور ایمان کی حالت میں وفات پاتا ہے، مرضیہ رکھا گیا ہے.اگر كَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا کے ہم یہ معنے کریں کے وہ ہر شخص جس سے خدا راضی ہو نبی سے بالا ہوتا ہے تو ہمیں تسلیم کرنا پڑیگا کہ ہر مومن جو نفسِ مطمئنہ رکھتا ہے وہ نبی سے بالا مقام رکھتا ہے.یا صِدِّیْقًا نَبِیًّا کے ماتحت کہنا پڑیگا کہ صدیق کا لفظ جس کے متعلق آئے وہ نبی سے بالا ہوتا ہے.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متعلق آتا ہے کہ قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا١ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ (الحجرات :۱۵) یعنی اعراب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آکر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں.تُو کہہ دے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے.ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ورنہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا.گویا اسلام ایمان کا ابتدائی درجہ ہے مگر اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے.اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ١ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (البقرة:۱۳۲).یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اُس کے رب نے کہا کہ تو اسلام لا.یعنی ہماری فرمانبرداری اختیار کر تو انہوں نے کہا کہ خدایا َمیں تو پہلے ہی تمام جہانوں کے رب کی فرمانبرداری اختیار کر چکا ہوں.یہ حکم ان کو نبوت کے بعد ہوا اور انہوں نے اَسْلَمْتُ کہا.جس کی خدا تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی اور ادھر اٰمَنَّا کہنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اَسْلَمْنَا کہو.ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام ایمان سے بھی ادنیٰ تھا اگر شیعوں والے معنے لئے جائیں تو اس کا یہ
Page 446
مطلب ہو گا کہ ہر اسلام لانے والا اور اپنے آپ کو مسلم کہنے والا نبی سے بالا ہو جاتا ہے.کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ مسلم بن جائو اورا نہوں نے اَسْلَمْتُ کہا.اسی طرح اگر امامت نبوت کے بعد ملنے کے یہ معنے ہیں کہ امام نبی سے بڑا ہوتا ہے تو پھر امامت تو الگ رہی ان معنوں کو تسلیم کرتے ہوئے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ ہر مسلم کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد امامت ملی.اسی طرح نبوت کے بعد انہیں مسلم بھی بننا پڑا.اس صورت میں ہر مسلم نبی سے بڑا ہو جاتا ہے.پس خالی امامت نبوت سے بڑی نہیں ہوتی بلکہ وہ امامت جو نبوت کے بعد ملتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے.جس طرح خالی اسلام نبوت سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ اسلام جو نبوت کے بعد حاصل ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے.غرض ہر چیز کا الگ الگ دائرہ ہے.ایک اسلام وہ ہے جو ایمان سے ادنیٰ ہوتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جو ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک اسلام وہ ہے جو نبوت کے بعد حاصل ہوتاہے.جیسے مانیٹر کا لفظ ایک ہی ہے مگر ایک ادنیٰ جماعت کا مانیٹر ہوتا ہے اور ایک بڑی جماعت کا.اب ادنیٰ جماعت کے مانیٹر ہونے کے یہ معنے نہیں ہوتے کہ وہ اونچی کلاس کے مانیٹر سے بھی بالا ہے.اس کا علم تو ایک بڑی جماعت کے طالبعلم سے بھی کم ہوتاہے.اسی طرح وہ امامت جو نبوت سے الگ ہوتی ہے اُسے اس امامت سے جو نبوت کے بعد ملتی ہے کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی.خود مسلمانوں میں دیکھ لو کہ نماز پڑھا نے والا امام کہلاتا ہے.پھرخلیفہ بھی امام ہوتا ہے اور نبی بھی امام ہوتا ہے.اِدھر قرآن کریم میں یہ دُعا سکھلائی گئی ہے وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا (الفرقان:۷۵)کہ الہٰی کچھ مومن بھی میرے مقتدی بنا دے اور مجھے اُن کا امام بنا اب کیا اس کے یہ معنے ہوںگے کہ ہر شخص یہ دُعا کرتا ہے کہ اُسے نبیوں سے بالا درجہ مل جائے؟ اگر اس کے یہ معنے ہوں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبیوں سے بالا درجہ بھی مل سکتا ہے کیونکہ اس کی دُعا سکھائی گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص نبی سے بڑا درجہ پا سکتا ہے.حالانکہ اس کے شیعہ بھی قائل نہیں.درحقیقتاِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کے معنے یہ ہیں کہ اے ابراہیم! تو اپنی قوم کے لئے نبی تھا مگر چونکہ تو آزمائشوں میں ثابت قدم نکلا ہے اور تُو نے بڑی دلیری سے میرے حکم کو مانتے ہوئے اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسے جنگل میں جا کر بسا دیا ہے جہاں پانی کا ایک قطرہ اور گھاس کی ایک پتی تک نہ تھی اور تُو نے اپنی اور اپنے خاندان کی موت قبول کر لی ہے اس لئے میں بھی تجھے یہ انعام بخشوںگا کہ تیرا یہ واقعہ ساری دنیا کے لوگوں کے لئے قیامت تک بطور نمونہ قائم رہیگا.اور جب بھی دنیا کو آزمائشوں اور امتحانوں میں ثابت قدم رہنے کا درس دیا جائے گا تو اس وقت تیرے اس واقعہ کو نمونہ کے طور پر پیش کیا جائے گا.یہی وجہ ہے کہ وَ اِذِ ابْتَلٰۤى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ١ؕ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا
Page 447
ورنہ اگر یہ کوئی الگ عہدہ ہوتا تو آزمائشوں کے ذکر کے ساتھ اس کے بیان کرنے کے کوئی معنے نہ تھے.حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتلائوں میں شاندار کامیابی کے ذکر کے معًا بعد اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کہنا بتاتا ہے کہ اس میں اسی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تیری زندگی کا یہ درخشاںواقعہ ہمیشہ کے لئے مشعل راہ کا کام دے گا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے تو ایک نمونہ کے طور پر پیش کیا جائے گا.قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ.جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئندہ زمانہ کی یہ خبر دی گئی توانہیں خیال آیا کہ جب میں بعد میں آنے والوں کا امام بنایا جاؤںگا تو میری طرف منسوب ہونے والی ذرّیت کی ہدایت کا بھی سامان ہونا چاہیے.چنانچہ انہوں نے کہا کہ الٰہی میری اولاد پر بھی تیری رحمت کا ہاتھ رہے.فرمایا.ٹھیک ہے مگر میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا.اِس سے یہ مراد نہیں کہ اُن کی ساری ذرّیت ظالم ہو جائے گی.بلکہ مطلب یہ ہے کہ اولاد دو قسم کی ہو گی.ایک ظالم اور ایک مطیع و فرمانبردار.اللہ تعالیٰ نے ظالم اولاد کی نفی کی ہے اور مطیع اولاد میں سے امام بنانے کا وعدہ کیا ہے.لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَکے دو۲ طرح معنے ہو سکتے ہیں.ایک یہ کہ عہدبمعنی معہود ہو یعنی جس چیز کا عہد کیا گیا ہے وہ ظالموں کو نہیں ملے گی.دوسرے معنے یہ ہیں کہ میں ظالموں کے لئے کوئی عہد نہیں کرونگا.صرف غیر ظالموں کیلئے کرونگا.یعنی جو قوم بحیثیت قوم ظالم بن جائےگی اس میں سے سلسلہء نبوت منقطع ہو جائے گا.اِس آیت سے ظاہر ہے کہ (۱)اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنانے کا وعدہ فرمایا (۲)حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی نسبت بھی اس وعدہ میں توسیع کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے مشروط وعدہ فرمایا.یعنی وعدہ کیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض اس عہد سے حصہ پائیں گے.مگر حصّہ پانے والے وہی ہوںگے جو قومی ظلم کے ذریعہ سے اپنے آپ کو انعام سے محروم نہ کر چکے ہوں.جب تک بنی اسرائیل اس وعدہ کے مستحق رہے اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرتا رہا.مگر جب بنی اسرائیل کلّی طور پر اس عہد کے انعامات کے ناقابل ہو گئے تو وہ عہد بنی اسرائیل کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا.بائیبل میں بھی اس عہد کے مشروط ہونے کا ذکر آتا ہے.چنانچہ پیدائش باب۱۷ آیت ۹ تا ۱۴ میں لکھا ہے : ’’پھر خدا نے ابراہام سے کہا.کہُ تو اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت میرے عہد کو نگاہ رکھیں.اور میراعہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد
Page 448
رکھو.سویہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرو.اور یہ اُس عہد کا نشان ہو گا.جو میرے اور تمہارے درمیان ہے.تمہاری پشت در پشت ہر لڑکے کا جب وہ آٹھ روز کا ہو ختنہ کیا جائے گا.کیا گھر کا پیدا.کیا پردیسی سے خریدا ہوا جو تیری نسل کا نہیں.لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زرخرید کا ختنہ کیا جائے.اور میرا عہد تمہارے جسموں میں عہد ابدی ہو گا اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہیں ہوا وہی شخص اپنے لوگوں میں سے کٹ جائے کہ اُس نے میرا عہد توڑا.‘‘ اِن آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اُن کی اولاد کی نسبت جو عہد کیا گیا تھا وہ مشروط تھا اور اس کی ظاہری علامت ختنہ تھا.اور صاف طور پر کہہ دیا گیا تھا کہ تیری اولاد میں سے جو اِس عہد کی پابندی نہیں کریں گے.خدا تعالیٰ کا عہد بھی اُن سے کوئی نہیں رہے گا.اوراُن کو وہ انعامات نہیں ملیں گے جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے وعدہ کیا گیاہے.اس عہد کا ظاہری نشان جو ختنہ کی صورت میں قائم کیا گیا تھا بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا اور یہ قوم خدا تعالیٰ کے انعامات کی وارث رہی.مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگئے تو بنی اسرائیل کا وہ حصّہ جو اُن پر ایمان نہ لایا تھا اس گروہ سے کٹ گیا جس کو انعامات کا وعدہ دیا گیا تھا اور صرف وہی لوگ انعامات کے مستحق رہ گئے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے.لیکن آگے چل کر انہوں نے بھی عہد توڑ دیا.اور ختنہ جو اس عہد کا ایک ظاہری نشان تھا اسے ترک کر دیا.غرض اس قوم کا کچھ حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے خدائی انعامات سے محروم ہو گیا اور جنہوں نے مانا تھا انہوں نے ختنہ چھوڑ کر اور شریعت کو لعنت قرار دیکر اپنے آپ کو خدائی فضلوں سے محروم کر لیا.اور یہ وعدہ بنواسحاق سے بنواسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا.اور میرے نزدیک اس جگہ یہی ذکر ہے کہ امامت کا مقام بنو اسحاق کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ بحیثیت جماعت ظالم ہوجانے والے تھے.ہاں بنو اسمٰعیل کو ملے گا.کیونکہ وہ بحیثیت جماعت کبھی ظالم نہیں ہوںگے.بلکہ ہر زمانہ میں اُن میں ایسے لوگ ہوتے رہیں گے جو خدا تعالیٰ کی وحی کے قائل ہوں گے.چنانچہ اِسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کا امام بنایا گیا.اور آپؐ کی امت میں سے اِس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ مقام بخشا گیا.
Page 450
بے معنی نہیںہوتا بلکہ معنوں پر زیادہ زور دینے کےلئے لایا جاتا ہے.اور اُسے زائدہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا.اس جگہ وَاتَّخِدُوْا پر زور دیا ہے کیونکہ یہ فعل کے معنوں میں شدّت پیدا کر دیتا ہے.مُصَلًّی : جائے نماز کو کہتے ہیں.عَھدَ : کے معنے ہیں اَوْصَاہُ وَشَرَطَ اِلَیْہِ.(اقرب)اُسے تاکید کی اور اُس کی پابندی اُس کے لئے ضروری قرار دی.مفرداتِ راغب میں لکھا ہے.اَلْقٰی اِلَیْہِ الْعَہْدَ وَاَوْصَاہُ بِحِفْظِہٖ.یعنی اُسے عہد سے واقف کیا اور اس عہد کی حفاظت کی.اُسے تاکید کی.پس اِس کے معنے یہ ہیںکہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیھما السلام کو وصیت کی اور اس کی پابندی اُن پر فرض کی.رُکَّعٌ.رَاکِعٌ کی جمع ہے اور رکوع کے معنے رکوع کرنے یا توحید پر چلنے کے ہوتے ہیں.(مفردات) سُجُوْدٌ.سَاجِدٌ کی جمع ہے.اس کے معنی (۱)سجدہ کرنے والے (۲)کامل فرمانبردار کے ہوتے ہیں.(اقرب) طَائِفٌ.جو شخص بار بار کسی جگہ آئے یااس کے گرد چکر لگائے وہ طائف کہلاتا ہے.(مفردات) عَاکِفٌ.بیٹھنے والا.جو دھرنا مار کر بیٹھ جائے.اِسی سے اعتکاف نکلا ہے.(مفردات) تفسیر.اَلْبَیْت خانہ کعبہ کا نام ہے.اسے اَلْبَیْت اس لئے کہتے ہیں کہ اِس میں بیت کے تمام خواص جمع ہیں.جیسے کہتے ہیں زَ یْدُنِ الرَّجُلُ زید ہی آدمی ہے.اورمراد یہ ہوتی ہے کہ ایک معقول آدمی کے اندر جس قدر خوبیاں پائی جانی چاہئیں وہ سب کی سب زید میں پائی جاتی ہیں.پس خانہ کعبہ ہی گھر ہے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی جو خصوصیتیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب صرف اِسی گھر سے حاصل ہوتی ہیں.گھر کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں.گھر کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ (۱)گھر مستقل رہائش کی جگہ ہوتی ہے (۲)گھر چوری اور ڈاکہ سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے (۳)گھر امن کا مقام ہوتا ہے جس میں داخل ہو کر انسان ہر قسم کے مصائب سے نجات پا جاتا ہے (۴)گھر تمام قریبی رشتہ داروںاور عزیزوں کے جمع ہونے کی جگہ ہوتا ہے (۵)گھر انسان کے مال و متاع کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہوتا ہے.اِن پانچ خصوصیتوں کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو در حقیقت خانہ کعبہ ہی اصل گھر ہے.کیونکہ اگر حفاظت کو لو تو بڑے بڑے قلعوں کو لوگ تباہ کر دیتے ہیں.بڑے بڑے شہروں میں رہنے والوں کولوگ تباہ کر دیتے ہیں.مگر خانہ کعبہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی دائمی حفاظت حاصل ہے.اور ہر شخص جو اس پر ہاتھ اٹھانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو شل کر دیتا ہے.چنانچہ ابرہہ کی مثال اِس بارہ میں ایک زندہ جاوید مثال ہے.ابرہہ جو
Page 451
ایبے سینیا کی عیسائی حکومت کی طرف سے یمن کا گورنر مقرر تھا.اس نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو تباہ کر دے اور عربوں کو مجبور کرے کہ وہ بیت اللہ کی بجائے صَنْعَاء کے گر جا کا حج کیا کریں.تاکہ عیسائیت کو فروغ حاصل ہو.جب وہ اپنے لائو لشکر کے ساتھ مکہ کے قریب پہنچا.تو اُس نے ایک خاص آدمی مکّہ والوں کی طرف بھجوایا.اور اُسے یہ پیغام دیا کہ میں صرف خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے آیا ہوں.تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں.اس لئے اگر تم میرے ارادہ میں مزاحم نہ ہو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہو ںگا اور کعبہ کو گرا کر واپس چلاجاؤںگا.وہ شخص جب مکّہ پہنچا.تواُس نے دریافت کیا کہ مکہ والوں کا آجکل سردار کون ہے.انہوں نے حضرت عبدالمطلب کا نام لیا.وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے ابرہہ کا پیغام دیا.حضرت عبدالمطلب نے اُسے جواب دیا کہ اگر اس کی ہم سے لڑنے کی نیت نہیں تو ہم بھی اُس سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ ہم میں تو اُس سے لڑائی کی طاقت ہی نہیں.باقی اس گھر کے متعلق ہمارایہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے.پس اگر اللہ تعالیٰ اس گھر کو بچانا چاہے تو یہ اُس کا کام ہے ہم میں ابرہہ اور اُس کے لشکر کے مقابلہ کی کوئی طاقت نہیں.اس پر اُس شخص نے کہا کہ اگر آپ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ابرہہ سے ملاقات کر یں.ابرہہ نے بھی خواہش کی تھی کہ میں مکہ کے کسی رئیس کو اپنے ساتھ لاؤں.اِس سے اُس کا دل خوش ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ ہی ترک کر دے.اس پر حضرت عبد المطلب نے بعض رؤساء اور اپنے لڑکوں کو ساتھ لیا اور ابرہہ کی ملاقات کے لئے چل پڑے.ابرہہ آپ سے مل کر بڑا متاثر ہوا اور اُس نے کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے.آپ فرمائیں کہ آپ کی اس ملاقات کا مقصد کیا ہے ؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا.کہ آپ کے لوگ چھاپہ مار کر کچھ اونٹ لوٹ لائے ہیں جن میں میرے بھی دو سو۲۰۰ اونٹ ہیں وہ مجھے واپس دلا دیئے جائیں.یہ سن کر اُسے غصہ آگیا اور کہنے لگا.میں نے تو آپ کو بڑا عقلمند سمجھا تھا اور میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں خانہ کعبہ پر حملہ نہ کروں مگر آپ نے خانہ کعبہ کا نام تک نہیں لیا اور اپنے دو سو ۲۰۰اونٹوں کا مطالبہ کر دیا ہے حالانکہ خانہ کعبہ کے مقابلہ میں دو سو اونٹوں کی حیثیت ہی کیا تھی کہ آپ اس کا ذکر کرتے.حضرت عبدالمطلب نے بیساختہ جواب دیا کہ اگر عبدالمطلب کو اپنے دو سو اونٹ کی فکر ہے تو کیا خدا تعالیٰ کو اپنے گھر کی حفاظت کا فکر نہ ہو گا.وہ آپ اس کی حفاظت کرے گا.مجھے تو صرف اپنے اونٹوں کی ضرورت ہے.ابرہہ یہ سُن کر طیش میں آگیا اور اُس نے اونٹ تو واپس کر دئیے مگر بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ زیادہ مضبوط کر لیا.ابھی اُس نے حملہ نہیں کیا تھا کہ تمام فوج میں چیچک کی بیماری پھوٹ پڑی اور
Page 452
لوگ کتوں کی طرح مرنے لگے.آخر اتنی بھاگڑ مچی کہ وہ محاصرہ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ہزاروں انسان وادیوں میں بھٹک بھٹک کر مر گئے.(السیرة النبویۃ لابن ہشام، امر الفیل...) غرض اَلْبَیْت میں بتایا ہے کہ حقیقی حفاظت لوگوں کو اِسی گھر کے ذریعہ میسّر آسکتی ہے.یہ خدا کا گھر ہے جس پر کوئی دشمن حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا.گھر کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مستقل رہائش کا مقام ہوتا ہے.اس لحاظ سے بھی یہی گھر ہے جو اَلْبَیْتکہلانے کا مستحق ہے کیونکہ دائمی زندگی خدا کے گھر میں ہی ملتی ہے.جو لوگ خدا تعالیٰ کے گھر میں نہیں جاتے اُن کی زندگی کیا زندگی ہے.دنیوی گھر کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَتَاعٌ قَلِیْلٌ وہ ایک قلیل متاع ہے.لیکن اپنے گھر کے متعلق فرماتا ہے.فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ.وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.(الفجر: ۳۰،۳۱)یعنی جب انسان خدا تعالیٰ کا سچا پرستار بن جاتا ہے اور اُس کا گھر مسجد ہو جاتا ہے تو پھر وہ جنّت میں داخل ہو جاتا ہے.غرض یہی بیت ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے.گھر کی تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر مختلف قسم کے ذخائر اور اموال وامتعہ رکھتا ہے.اِس نقطۂ نگاہ سے بھی یہی گھر ہے جو رُوحانی برکات کے ذخائر اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے.کیونکہ اورذخائر تو خواہ کتنے بھی قیمتی ہوں ضائع ہو جاتے ہیں لیکن جو وقت عبادت الہٰی میں خرچ ہوتا ہے وہ ضائع نہیں جاتا بلکہ ایک ایک لمحہ جو ذکر الٰہی اور عبادت میں بسر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے ہزاروں ہزار انعامات کے ذخائر کی صورت میں محفوظ رکھتا اور اپنے بندے کو اس سے متمتع فرماتا ہے.گھر کی چوتھی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے جمع ہونیکی جگہ ہوتی ہے.یہ خصوصیت بھی خانہ کعبہ میں بدرجہ اَتَم پائی جاتی ہے.کیونکہ تمام دنیا کے مسلمان وہاں ہرسال حج کے لئے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر اپنے ایمان تازہ کرتے ہیں اور پھر اس لحاظ سے بھی خانہ کعبہ سب لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے کہ وہ جگہ جہاں انسان اپنے تمام رشتہ داروں سے مِل سکے گا صرف جنّت ہے اور جنّت کاظل مسجد ہوتی ہے جس میں پانچوں وقت تمام مسلمان جمع ہو کر خدا تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے بھی با خبر رہتے ہیں.پھر گھر کی یہ خصوصیتکہ اس میں انسان کو ہر قسم کا امن حاصل ہوتا ہے یہ بھی خانہ کعبہ کو میّسر ہے.کیونکہ امن اسی صورت میں میّسر آتا ہے جب تمام جھگڑے مٹ جائیں اور خانہ کعبہ ہی ایک ایسا مقام ہے جو توحید کا مرکز ہونے
Page 453
کی وجہ سے تمام دنیا کو ایک نقطۂ اتحاد پر جمع کرنے کا ذریعہ ہے.غرض خانہ کعبہ ہی حقیقی اور کامل گھر ہے جس میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک گھر میں پائی جانی چاہئیں.مَثَا بَۃً لِّلنَّاسِ: مَثَابَةَکے معنے تفرقہ کے بعد اکٹھے ہونے کی جگہ کے ہیں اس میں بتایا کہ بیت اللہ کا قیام اس لئے عمل میں آیا ہے کہ ساری دنیا کو ایک مرکز پر جمع کردیا جائے اوروہ لوگ جو متفرق ہو چکے ہیں اس گھر کے ذریعہ پھر اکٹھے کر دیئے جائیں.یعنی ایک عالمگیر مذہب کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور ساری دنیا کو یہ گھر جمع کرنے کا ذریعہ ہو گا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مختلف انبیاء نے اپنے اپنے زمانہ میں اتحاد پیدا کیا ہے.مگر جہاں وہ ایک ایک قوم کے درمیان اتحاد پیدا کرتے وہاں وہ دنیا میں اختلاف بھی پیدا کرتے تھے.جیسے بنی اسرائیل کے لئے ضروری تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلیں.حضرت کرشنؑ کے متبعین کے لئے ضروری تھا کہ وہ اُن کے پیچھے چلیں.ایرانیوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ زرتشت ؑ کے پیچھے چلیں.اس طرح اگر انہوں نے ایک طرف اپنی اپنی قوم میں اتحاد پیدا کیا تو دوسری طرف مختلف ممالک کے درمیان اختلاف بھی پیدا کر دیا.یہ صرف خانہ کعبہ ہی ہے جسے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ تمام قوموں کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا ہے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ فرمایا کہ آپ ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے ہیں اور پھر آپ نے یہ بھی دعویٰ فرمایا کہ تمام متفرق قوموں اور جماعتوں کو میرے ذریعے دین واحد پر اکٹھاکر دیا جائے گا.دیکھو کس عجیب رنگ میں اور کس شان و شوکت سے یہ پیشگوئی پوری ہوئی.آخر مختلف اقوامِ عالم کے ایک جگہ جمع کر دینے کی خبر سوائے خدا کے اور کون دے سکتا تھا اور آئندہ جو کچھ مقدّر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے.چنانچہ حضرت مسیح موعو د علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے ذریعے سب قوموں کو اکٹھا کر دےگا.اور ایک وقت ایسا آئےگا کہ اشرار چوہڑوں اور چماروں کی طرح رہ جائیں گے.آپ فرماتے ہیں: ’’شیطان نے آدم ؑ کو مارنے کا منصوبہ کیا تھا اور اس کا استیصال چاہا تھا پھر شیطان نے خدا سے مہلت چاہی اور اُس کو مہلت دی گئی.اِلٰی وَقْتٍ مَّعْلُوْمٍ (یعنی ایک معلوم وقت تک) بسبب اس مہلت کے کسی نبی نے اس کو قتل نہ کیا.اُس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرر تھا کہ وہ مسیح موعود ؑ کے ہاتھ سے قتل ہو.اب تک وہ ڈاکوؤں کی طرح پھرتا رہا.لیکن اب اُس کی ہلاکت کا وقت آگیا ہے.اب تک اخیار کی قلّت اور اشرار کی کثرت تھی.لیکن شیطان ہلاک ہو گا اور اخیار کی کثرت ہو گی اور اشرار چوہڑے چماروں کی طرح ذلیل بطور نمونہ کے رہ جائیں گے.‘‘ (الحکم جلد ۵ نمبر ۳۴ مورخہ ۱۷ ؍ستمبر ۱۹۰۱ء صفحہ ۱۱)
Page 454
میرے نزدیک اس پیشگوئی کے کامل طور پر پورے ہونے کا زمانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہی ہے.کیونکہ بنو اسحاق اور بنو اسماعیل دونوں کی شاخیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے وجود میں آخر مل گئی ہیں.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرہ سو سال کے بعدیہ پیشگوئی پوری ہو رہی ہے اور یورپ امریکہ افریقہ آسٹریلیا ہندوستان اور دیگر ممالک کے باشندے یعنی چینی جاوی سماٹری ایرانی عیسائی ہندو مغل پٹھان راجپوت غرضیکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ اسلام اور احمدیت کو قبول کر رہے ہیں.اور یہ پیشگوئی سچی ثابت ہو رہی ہے کہ بیت اللہ کو ہم نے متفرق لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا ذریعہ بنایا ہے.اَمْنًا : دوسری پیشگوئی یہ فرمائی کہ (۱)یہ مقام امن والاہو گا.یعنی اسے دوسروں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا.(۲)یہ مقام لوگوں کو امن دینے والا ہو گا.اور چونکہ حقیقی امن اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے اس لئے اَمْنًاکے تیسرے معنے یہ بھی ہیں کہ اطمینان قلب بخشنے والا.اطمینان قلب کے لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اسلام سے باہر انسان کو اطمینان قلب کہیں حاصل نہیں ہو سکتا.اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ اسلام دلیل سے اپنی بات منواتا ہے جبکہ دوسرے مذاہب دلیل کی بجائے جبراور تحکّم سے کام لیتے ہیں.اسلام کہتا ہے کہ جو شخص بغیر دلیل کے کوئی بات مانتا ہے اس کے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرواتا ہے کہ عَلٰی بَصِیْرَ ۃٍ اَ نَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِیْ (یوسف : ۱۰۹) یعنی میں جس تعلیم کو پیش کرتا ہوں.اُسے دلائل سے مانتا ہوں اور میرے متبعین بھی اسے دلائل سے مانتے ہیں.پس میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں.تم کہتے ہو کہ فلاں بات مان لو ورنہ جہنم میں جاؤ گے لیکن میں جو کہتا ہوں اس کے ساتھ اس کی معقولیت کی دلیل بھی دیتا ہوں کیونکہ اس کے بغیر اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا.پھر اطمینان قلب کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ مشاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہو جانا ہے.اگر یہ بات کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اُسے کوئی چیز پریشان نہیں کر سکتی.اسلام خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والوں کو اس کی بھی خوشخبری دیتا ہے اور فرماتا ہے.يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ.ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ.وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.( الفجر:۲۸تا۳۱) یعنی اے نفسِ مطمئنہ ! اپنے رب کی طرف اس حالت میں َلوٹ کہ تو اس سے خوش ہے اور وہ تجھ سے خوش.پس آ اور میرے بندوں میں داخل ہو جا.آاور میری جنّت میں داخل ہو جا.یوں تو سب مذاہب کے پیرو کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے مطابق عمل کرو تو تم جنّت میں چلے جاؤگے.مگر اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہیں صرف مرنے کے بعد جنّت ملے گی بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں تمہیں خدا دکھادیتا ہوں جو
Page 455
اس بات کا ثبوت ہو گا کہ َمیں حق پر ہوں.وہ فرماتا ہے.اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (حٰمٓ السّجدة:۳۱) یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر مستقل مزاجی سے اس عقیدہ پر قائم ہو گئے اُن پر ملائکہ یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور نہ کسی پچھلی کوتاہی کا غم کرو اور اس جنّت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ.جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے.غرض اسلام اطمینان قلب پیدا کرنے کا مدعی ہے جبکہ اور کوئی مذہب اس کا دعویٰ نہیں کرتا.اَمْنًا کے دوسرے معنے امن میں آنے والے کے ہیں.یہ معنے بھی خانہ کعبہ پر چسپاں ہوتے ہیں.کیونکہ دشمنوں کے بار بار کے منصوبوں کے باوجود یہ مقام خدا تعالیٰ کی مدد سے محفوظ چلا آتا ہے حکومتوں کے بعد حکومتیں بدلیں اور ملکوں کے بعد ملک برباد ہوئے لیکن بیت اللہ دشمنوں کے حملوں سے محفوظ اور مقام امن ہی رہا.پھردنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کا معبد ہمیشہ اس کے قبضے میں رہا ہو.صرف اہل اسلام کا مقدس معبد ہمیشہ سے اس کے قبضہ میں رہا ہے.یروشلم جو یہودیوں اور مسیحیوں کا متبرک مقام ہے ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا.ہر دوار اور بنارس جو ہندوؤں کے متبرک مقامات ہیںچھ سات سو سال تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہے اور پھر انگریزوں کے قبضہ میں چلے گئے.اسی طرح گیا جوبدھوؔں کا متبرک مقام ہے پہلے مسلمانوں کے قبضہ میں رہا.پھر انگریز اس پر قابض ہوئے اور اب ہندوؤں کا اس پر قبضہ ہے یہی حال جینیوں کا ہے.ان کے معبد کبھی کسی کے قبضہ میں رہے اور کبھی کسی کے قبضہ میں.مگر خانہ کعبہ صرف مسلمانوں ہی کے ہاتھ میں رہا اور کبھی کوئی غیر حکومت اُسے اپنے قبضہ میں لینے میں کامیاب نہیں ہوئی.پس یہ ہمیشہ مقام امن ہی رہا.امن دینے کے لحاظ سے جو خانہ کعبہ کو خصوصیت حاصل ہے اس کی مثال بھی دنیا میں کہیں نہیں ملتی.وہاں ہر چیز کو امن حاصل ہے.یہاں تک کہ جانوروں کو بھی امن حاصل ہے اور ان کا شکار منع ہے بلکہ درختوں کا کاٹنا تک منع ہے.سوائے اِذخر گھاس کے.انسانوں کو یہ امن حاصل ہے کہ حدودِ حرم میں لڑائی ممنوع ہے (بخاری کتاب المغازی باب ۵۴ مقام النبی بمکة زمن الفتح).اور پھر انسان کو تقویٰ اور روحانیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہوتی ہے.وہ مزید براں ہے.مگر تعجب ہے کہ وہی گھرجسے خدا نے امن دینے والا قرار دیا ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ایسے جہاد کے قائل ہیں جو دنیا میں کسی کو پناہ نہیں دیتا یہ عجیب تماشہ ہے کہ جس مذہب کو امن والا کہا گیا تھا اُسی کو فساد والا قرار دیا جاتا ہے اور اس طرح اضداد کو جمع کر دیا جاتا ہے.اس کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ
Page 456
ہم لوگوں کو بتائیں کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں.وہ اپنے اندر امن کی تعلیم رکھتا ہے.اور دوسروں کو بھی امن دیتا ہے اور اِسی مقصد کیلئے خانہ کعبہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا.غرض فرمایا کہ تم اس وقت کو یاد کرو.جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کیلئے مثابہ بنایا.یعنی تمام دنیا کیلئے نسل اور قومیت کے امتیاز کے بغیر اور ملک اور زبان کے امتیاز کے بغیر اس کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں.اسی طرح مثابہ اس منڈیر کو بھی کہتے ہیں جو کنوئیں کے اردگردبنائی جاتی ہے اور جس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ جب زور کی ہوا چلے تو کوڑا کرکٹ اور گوبر وغیرہ اُڑ کر اند رنہ چلا جائے.یا کوئی اور گندی چیز کنوئیں کے پانی کو خراب نہ کر دے.اسی طرح منڈیر سے یہ غرض بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص غلطی سے کنوئیں میں نہ گرجائے.غرض منڈیر کا مقصد کنوئیں کو برُی چیزوں اور لوگوں کو گرنے سے بچانا ہوتا ہے.اس نقطہ ٔ نگاہ کو مدِّنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو ایک تو اس غرض کے لئے بنایا ہے کہ دنیا کے چاروں طرف سے لوگ اِس جگہ آئیں اور یہاں آکر دینی تربیت اور اعلیٰ اخلاق حاصل کریں.اور دوسرے ہم نے خانہ کعبہ کو اس لئے بنایا ہے تاکہ وہ دنیا کیلئے منڈیر کا کام دے اور ہر قسم کی برائیوں اور شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے.تیسرے ہم نے اسے امن کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے.گویا جس طرح قلعہ اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ فوج وہاں جمع ہو کر اپنے نظام کو مضبوط کر سکے اسی طرح خدا تعالیٰ نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مقام بنایا ہے.اور جس طرح قلعہ کی یہ غرض ہوتی ہے کہ ناپسندیدہ عناصر اندر نہ آسکیں اِسی طرح بیت اللہ کو خدا نے منڈیر بنایا ہے تاکہ غیر پسندیدہ عناصر اس سے دُور رہیں.پھر قلعہ کی تیسری غرض اردگرد کے علاقہ کی حفاظت کر کے امن قائم رکھنا ہوتی ہے.یہ غرض بھی بیت اللہ میں پائی جاتی ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اَمْنًا کہہ کر اسی امر کی طرف اشارہ کیا ہے.اور بتا یا ہے کہ اسے قیام امن کیلئے بنایا گیا ہے.گویا بیت اللہ نظام کے قیام کا مرکز بھی ہے.غیرپسندیدہ عناصر کو دُور کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور دنیا کے امن کے قیام کا سبب بھی ہے.وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى.اس آیت میں مِنْ یا تو تاکید کیلئے آیا ہے.یا تمیز کیلئے اور وَاتَّخِذُوْا سے پہلے قُلْنَا یا اَمَرْ نَا محذوف ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم نے کہا یا ہم نے حکم دیا کہ تم شدت کے ساتھ مقام ابراہیم کو عبادت گاہ بناؤ.یا جہاں انہوں نے خانہ کعبہ کو بنانے کیلئے قیام کیا تھا اس میں سے کسی جگہ نماز پڑھو.یا یہ کہ ابراہیم ؑ کے کھڑے ہونے کی جگہ پر یعنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے تم بھی طواف کے بعد اس شکریہ میں کہ خدا نے اس گھر کو دنیا کے جمع کرنے اورامن کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے نماز پڑھو.مقام ابراہیم کعبہ کے پاس ایک خاص جگہ ہے.جہاں طواف بیت اللہ کے بعد مسلمانوں کو دو۲ سنتیں پڑھنے کا
Page 457
حکم ہے.ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعداس جگہ شکرانہ کے طور پر نماز پڑھی تھی اور اس سنّت کو جاری رکھنے کیلئے وہاں دو ۲ رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے.لیکن میں سمجھتا ہوں.وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى میں جس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت اور فرمانبرداری کے جس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تم بھی اسی مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کرو.لوگ غلطی سے مقام ابراہیم ؑ سے مراد صرف جسمانی مقام سمجھ لیتے ہیں.حالانکہ ابراہیم ؑ کا اصل مقام وہ مقام اخلاص اورمقام تقویٰ تھا جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا.گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اُسی رنگ میں دین کیلئے قربانیاں بجالاؤجس رنگ میں ابراہیم ؑنے اللہ تعالیٰ سے محبت کی اور جس رنگ میں ابراہیم ؑ نے اللہ تعالیٰ کیلئے قربانیاں کیں.پس یہاں مقام ابراہیم سے مراد کوئی جسمانی مقام نہیں بلکہ روحانی مقام مراد ہے.ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں.کہ تم نے میرے مقام کو نہیں پہچانا.اب اگر کوئی شخص یہ الفاظ کہے تو دوسرا شخص یہ نہیں کرتا کہ اُسے دھکّا دے کر پرے پھینک دے اور کہے کہ تم جس مقام پر کھڑے تھے وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے.ہمیشہ ایسے الفاظ سے درجہ کی بلندی مراد ہوتی ہے.پس وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى کے یہی معنے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس اخلاص اور جس محبت اور جس تقویٰ اور جس انابت الی اللہ سے نیکیوں میں حصہ لیاتھا تم بھی اسی مقام پر کھڑے ہو کر اُن نیکیوں میں حصہ لو تاکہ تمہیں بھی ابراہیمی مقام حاصل ہو.اگر مقام ابرہیم کو مصلّٰی بنانے کے یہی معنے ہوں کہ ہر شخص اُن کے مصلّٰی پر جا کر کھڑ ا ہو.تو یہ تو قطعی طور پر نا ممکن ہے.اوّل تو یہ جھگڑا رہتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نماز پڑھی تھی یا وہاں.اور اگر بالفرض یہ یقینی طور پر پتہ لگ بھی جاتا کہ انہوں نے کہاں نماز پڑھی تھی تو بھی ساری دنیا کے مسلمان وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے.صرف حج میں ایک لاکھ سے زیادہ حاجی شامل ہوتے ہیں.اگر جلدی جلدی بھی نماز پڑھی جائے.تب بھی ایک شخص کی نماز پر دو منٹ صرف آئینگے اس کے معنے یہ ہوئے کہ ایک گھنٹہ میں تیس اور چوبیس گھنٹہ میں سات سو بیس آدمی وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں.اب بتاؤ کہ باقی جو ۸۰ ۹۹۲ رہ جائیں گے وہ کیا کرینگے اور باقی مسلم دنیا کےلئے تو کوئی صورت ہی نا ممکن ہو گی.پس اگر اس حکم کو ظاہر پر محمول کیا جائے تو اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا.پھر ایسی صورت میں فسادات کا بھی احتمال رہتا ہے.بلکہ ایک دفعہ تو محض اسی جھگڑے کی وجہ سے مکّہ میںایک قتل بھی ہو گیا تھا.پس اس آیت کے یہ معنے نہیں.بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس مقام اخلاص پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی تم بھی اُسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو.
Page 458
پھر اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا کی طرف بھی اشارہ کیا ہے.اور یہ ہدایت دی ہے کہ تمہارا بھی ایک امام ہونا چاہیے تاکہ اِس طرح سنتِ ابراہیمی تم میں زندہ رہے.درحقیقت اِن دونوں آیات میں دو ۲امامتوں کا ذکر کیا گیا ہے.پہلے فرمایا کہ.اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا.اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں.اس پر ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ اے خدا !میری ذرّیت کو بھی اس مقام سے سرفراز فرما.کیونکہ اگر َمیں مرگیا تو کام کس طرح چلے گا.خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے تو ظالم بھی ہونے والے ہیں.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان ظالموں کے سپرد یہ کام کیا جائے.ہاں ہم تمہاری اولاد کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ سنّتِ ابراہیمی کو ہمیشہ قائم رکھیں جو لوگ ایسا کرینگے ہم اُن میں سے امام بناتے جائیں گے اور وہ خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ انعامات سے حصّہ لیتے چلے جائیں گے.پس اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو۲ امامتوں کا ذکر فرمایا ہے.ایک امامتِ نبوت کا جو خدا تعالیٰ کی طرف براہ راست ملتی ہے اور دوسری امامتِ خلافت کا جس میں بندوں کا بھی دخل ہوتا ہے.اور جس کی طرف وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى میں اشارہ کیا گیا ہے.اور بنی نوع انسان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جب امامتِ نبوت نہ ہو تو اُن کا فرض ہے کہ وہ امامت خلافت کو اپنے اندر قائم رکھا کریں.پھر وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى میں دنیا کے تمام اہم مقامات اور شہروں میں ایسے تبلیغی مراکز قائم کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو خانہ کعبہ کی ظلّیت میں اشاعت اسلام کے مراکز ہوں اور جہاں بیٹھ کر عبادتِ الٰہی کو قائم کیا جائے اور توحید کی اشاعت کی جائے.اللہ تعالیٰ بنی نوع انسان کو مخاطب کرتا اور انہیں فرماتا ہے کہ اے لوگو جو خانہ کعبہ کے شیدائی بنتے ہو.جو بیت اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو.تم ہر ایک چیز جو تمہیں پسند آتی ہے اس کی تصویر اپنے گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہو.اگر کوئی پھل تمہیں پسند ہو تو تم اُسے اپنے گھر لاتے اوراپنی بیوی بچوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہو.جب تم بازار میں خربوزہ دیکھ کر اُسے اپنے گھر میں لاتے ہو جب تم کسی اچھے نظارہ کو دیکھتے ہو تو اس کی تصویر کھینچتے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دکھاتے ہو تو کیا وجہ ہے کیاسبب ہے، اور اس میں کونسی معقولیت ہے کہ تم اپنے مونہوں سے تو خانہ کعبہ کی تعریفیں کرتے ہو.اپنے مونہوں سے تو خانہ کعبہ کے احترام کا اظہار کرتے ہو لیکن تم ایک خربوزے کو تو گھر میں لانے کی کوشش کرتے ہو.تم تاج محل کو دیکھتے ہو تو اس کی تصویر لینے کی کوشش کرتے ہو مگر تم خانہ کعبہ کے ظلّ کو اپنے ملک اور اپنے علاقہ میں لانے کی کوشش نہیں کرتے.خانہ کعبہ کیا ہے؟ ایک گھر ہے جو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے وقف ہے.مگر ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے انسان خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتے.پس جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابراہیم ؑ کی نقلیں دنیا میں پیدا ہوں اسی طرح وہ یہ بھی
Page 459
چاہتا ہے کہ تم خانہ کعبہ کی نقلیں بنائوجس میں تم اور تمہاری اولادیں اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لئے وقف کر کے بیٹھ جائیں.جس طرح وہ لوگ جو ابراہیم ؑ کے نمونہ پر چلیں گے.ابراہیم ؑ کی اولاد اور اس کا ظلّ ہوں گے.اسی طرح یہ نقلیں خانہ کعبہ کی اولاد ہونگی.خانہ کعبہ کی ظلّاور اس کا نمونہ ہوں گی.اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک خانہ کعبہ کے ظلّدنیا کے گوشہ گوشہ میں قائم نہ کر دیئے جائیں اُس وقت تک دین کبھی پھیل ہی نہیں سکتا.پس فرماتا ہے.وَ اتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى اے بنی نوع انسان! ہم تم کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ تم بھی ابراہیمی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرو یعنی ایسی مراکز بنائو جو دین کی اشاعت کا کام دیں کیونکہ اس کے بغیر اسلام کی کامل اشاعت کبھی نہیں ہو سکتی.وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآىِٕفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ اب بتاتا ہے کہ وہ مقامِ ابراہیم کیا چیز ہے ؟ فرماتا ہے.وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ اور ہم نے ابراہیم ؑ اور اسمٰعیل ؑ کو بڑی پکی نصیحت کی تھی.عَھِدَ بِہٖ کے معنے ہوتے ہیں اس نے فلاں کے ساتھ عہد کیا.لیکن عَھِدَ کے ساتھ جب اِلٰی کا صِلہ آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں پکّی نصیحت کرنا یا وصیت کرنا پس فرماتا ہے وَ عَهِدْنَاۤ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ ہم نے ابراہیم ؑاور اسمٰعیل کو بار بار نصیحت کی تھی اور بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی اور تاکیدی حکم دیا اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو اور اسے ہر قسم کے عیبوں اور خرابیوں سے بچائو.لِلطَّآىِٕفِيْنَ ا ن لوگوں کے لئے جو اس کے اردگرد طواف کرنیوالے ہیں یا اُن لوگوں کے لئے جو اس جگہ بار بار آنے والے ہیں.وَ الْعٰكِفِيْنَ اور ان لوگوں کے لئے جو اعتکاف کے لئے آئیں یا اپنی زندگی وقف کر کے یہیں بیٹھ جائیں.طائفین وہ لوگ ہیں جو کبھی کبھی آئیں اور عاکفین وہ ہیں جو اپنی زندگی اس گھر کے لئے وقف کردیں.وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ اور ان لوگوں کے لئے جو خدا تعالیٰ کی توحید کے قیام کے لئے کھڑے رہتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری میں اپنی ساری زندگی خرچ کرتے ہیں یا ان لوگوں کے لئے جو رکوع و سجود کرتے ہیں.اس جگہ رکوع و سجود سے ظاہری اور قلبی دونوں رکوع و سجود مراد ہیں.یعنی وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اس کے حضور رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوں.اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھنے والے ہوں اور جو اس کے کامل فرمانبردار ہوں.اسی طرح تطہیر کے بھی دونوں مفہوم ہیں اس سے مراد ظاہری صفائی بھی ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کو صاف رکھو اور اس میں عود وغیرہ جلاتے رہواور اس سے باطنی صفائی بھی مراد ہو سکتی ہے یعنی مسجد کی حرمت کا خیال رکھو.اور اس میں بیٹھنے کے بعد لغو یات سے کنارہ کش رہو.افسوس ہے کہ آجکل مساجد میں ذکر
Page 460
الہٰی کرنے کی بجائے لوگ اِدھر اُدھر کی گپیں ہانکتے رہتے ہیں حالانکہ مسجدیں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں بیشک ضرورت محسوس ہونے پر مذہبی ،سیاسی ، قضائی اور تمدنی امور پر بھی مساجد میں گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن مساجد میں بیٹھ کر گپیں ہانکنا اور اِدھر اُدھر کی فضول باتیں کرنا سخت ناپسندیدہ امر ہے.نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بارہ میں محتاط رہنا چاہیے.طَهِّرَا بَيْتِيَ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک زمانہ میں لوگوں نے اس کے اندر بُت رکھ دینے ہیں.تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان بُتوں کو نکالو اور بیت اللہ کو پاک و صاف کرو.لُغت کی رو سے بھی نجاست ظاہری اور باطنی دونوں کو دُور کرنے کے لئے تطھیر کا لفظ استعمال ہوتاہے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ و سلم نے بیت اللہ کی تطہیر کی اور تین سو ساٹھ بتوں سے اس کو پاک کر دیا(السیرة النبویۃ لابن ہشام، ذکر فتح مکة).آپ کا یہ فعل اسی وصیت کے مطابق تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسمٰعیل علیہما السلام کو فرمائی تھی کہطَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآىِٕفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ.یہ سورۃ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی اور وہ ایسا وقت تھا کہ مسلمان مدینہ میں بھی محفوظ نہ تھے.مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام دنیا جو اس وقت متفرق ہے وہ اس مرکز پر جمع ہو جائے گی چنانچہ دیکھ لو.اب ساری دنیا سے لوگ حج کے لئے جاتے ہیں اور ادھر مُنہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کی صداقت کا اور کیا نشان ہو سکتا ہے.وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اور (اس و قت کو بھی یاد کرو) جب ابراہیم ؑنے کہا تھا کہ اے میرے رب! اس (جگہ) کو ایک پرُامن شہر بنادے اور اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ١ؕ اس کے باشندوں میں سے جو بھی اللہ پر اور آنے والے دن پر ایمان لائیں انہیں (ہرقسم کے) پھل عطا فرما.(اس پر اللہ نے) قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ فرمایا.اور جو شخص کفر کرے اسے بھی میں تھوڑی مدت تک فائدہ پہنچائوں گا پھر اسے مجبور کر کے دوزخ کے عذاب کی
Page 461
النَّارِ١ؕ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ۰۰۱۲۷ طرف لے جائوں گا اور (یہ) بہت برا انجام ہے.حَلّ لُغَات.ثَمَرٰت کالفظ بالعموم نتائج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.اسی طرح ثمرات تازہ بتازہ پھلوں کو بھی کہتے ہیں.اَضْطَرُّہٗ : اِضْطَرَّ ہٗ اِلَیْہِ کے معنے ہیں اَحْوَجَہٗ وَاَلْجَا ءَ ہٗ اِلَیْہِ کسی چیز کو گھیر گھار کر اور مجبور کر کے ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا.(اقرب) اس لحاظ سے آیت کے معنے یہ ہیں کہ میں اُن کو گھیر گھار کر جہنم کی طرف لے جائوںگا.تفسیر.جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو مرجع خلائق اور امنِ عالم کا گہوارہ بنایاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور جُھک گئے اور انہوں نے دُعا کی رَبِّ اجْعَلْ ھٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا.کہ اے خدا ! توُ نے جو یہ کہا ہے کہ طواف اور رکوع و سجود کرنے والے لوگ یہاں آئیں گے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں آبادی ہو گی.پس میں تجھ سے دُعا کرتا ہوں کہ تو اس جگہ کو بَلَدًا اٰمِنًا بنا دے.یہاں کی آبادی خوب بڑھے اور پھولے پھلے.اور یہ ایک پُرامن شہر ہو.فتنہ و فساد اور لڑائیوں کی آماجگاہ نہ ہو.جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دُعا کی تھی.اُس وقت مکہ کوئی شہر نہیں تھا.صرف چند جھونپڑیاں تھیں جو ایک بے آب و گیاہ وادی میں نظر آتی تھیں.لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا یہ کی کہ یہ زمین جو ویران پڑی ہوئی ہے اسے ایک شہر بنادے.عام طور پر جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اس کے یہ معنے کیا کرتے ہیں کہ اس شہر کو امن والا بنا دے.حالانکہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی منشا ہوتا تو آپ ھٰذَا بَلَدًا کہنے کی بجائے ھٰذَا الْبَلَدَ فرماتے مگر آپ ھٰذَا الْبَلَدَ نہیں کہتے بلکہ ھٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا کہتے ہیں.پس یہ شہر کے بنانے کی دُعا ہے شہر کو کچھ اور بنانے کی دُعا نہیں وہ فرماتے ہیںرَبِّ اجْعَلْ هٰذَا اے میرے رب بنا دے اس ویران زمین کو بَلَدًا ایک شہر اٰمِنًا مگر شہروں کے ساتھ فتنہ و فساد کا بھی احتمال ہوتا ہے.جب لوگ مل کر رہتے ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جھگڑے بھی ہوتے ہیں.فسادات بھی ہوتے ہیں اور پھر شہروں کو فتح کرنے کے لئے حکومتیں بھی حملہ کرتی ہیں یا بعض شہر جب بڑے ہو جائیں تو اُن کے رہنے والے اپنا نفوذ بڑھانے کے لئے دوسروں پر حملہ کر دیتے ہیں اور چونکہ یہ سارے خدشات شہروں سے وابستہ ہوتے ہیں اس لئےمیں تجھ سے یہ دُعا کرتا ہوں کہ تو اسے امن والا بنائیو.نہ کوئی اس پر حملہ کرے اور نہ یہ کسی اور پر حملہ
Page 462
کرے تاکہ خانہ کعبہ کے قیام کا جو مقصد ہے وہ صحیح رنگ میں پورا ہو سکے.گویا جس امن کی پیشگوئی خانہ کعبہ کے متعلق تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ وہ ا س جگہ آباد ہونے والے شہر کی طرف بھی منتقل ہو جائے.درحقیقت خانہ کعبہ کی حرمت تو خدا تعالیٰ نے خود قائم فرمائی تھی مگر مکّہ مکرمہ کی حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے قائم ہوئی.اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے ایک موقعہ پر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا اور میں مدینہ کو حرم بناتاہوں.(بخاری کتاب الجہاد باب فضل الخدمة فی الغزوة) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دُعا میں مثابہ کا لفظ چھوڑ دیا ہے اور صرف امن کی دُعا مانگی ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک زائد دُعا کی ہے اور وہ یہ کہ اس گھر کے ساتھ ایک شہر بھی بن جائے اور وہ بھی امن والا ہو.اور محض کسی شہر میں آنا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے اس حصہ کو چھوڑ دیا کیونکہ عبادت اور ثواب صرف خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے مکّہ سے نہیں.پس آپ نے مثابۃ کو چھوڑ دیا اور امن کی دُعا کو لے لیا.جو خانہ کعبہ کے لئے بھی ضروری تھی اور اس کے ارد گرد آباد ہونے والوں کے لئے بھی ضروری تھی.اس دُعا سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے کلام کو پورا کرنے کے کس قدر حریص ہوتے ہیں اور وہ اس کے لئے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں.بعض لوگ نادانی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اگر فلاں الہام خدا تعالیٰ کا تھا تو مرزا صاحب نے اس کے پورا کرنے کی کیوں کوشش کی ؟ وہ یہ نہیںدیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائی کلام کے پورا کرنے کے لئے اس کے معًابعد دُعائیں کرنی شروع کر دیں حالانکہ جب خدا تعالیٰ فرما چکا تھا کہ اس گھر کو عاکفین کے لئے صاف ستھرا رکھو.تو اس کے معنے یہ تھے کہ یہاں لوگ مقیم بھی ہوںگے اور باہر سے بھی آئیں گے.گویا اس لفظ میں ایک شہر بن جانے کی خبر دیدی گئی تھی.پھر جو بات خدا تعالیٰ پہلے ہی منظور کر چکا تھا اس کے متعلق دُعا کرنے کے کیا معنے تھے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ خدا تعالیٰ جو خبر دیتا ہے اس کے متعلق مومنوں کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اُسے پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان کی طرف سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے دُعائیں کرتے ہیں کہ اُن کی غفلت کی وجہ سے وہ وعدہ ٹل نہ جائے.پھر دُعا کے ساتھ دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہری سامان مہیا کرتے ہیں.حدیثوں میں آتا ہے کہ جب حضر ت ہاجرہؓ اور اسمٰعیل علیہ السلام وہاں بس گئے.اور زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا تو انہی دنوں وہاں سے ایک قافلہ گزرا.انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں پانی کا وافر انتظام ہے تو انہوں نے حضرت ہاجرہؓ سے وہاں سکونت اختیار کرنے کی اجازت لی.حضرت ہاجرہؓ نے اُن کی اس درخواست کو قبول فرمالیا.اور انہیں وہاں پر رہائش کی اجازت دے دی(بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یزفون
Page 463
النسلان فی المشی).یہ مکّہ کی آبادی کی دوسری تدبیر تھی کہ قافلہ والوں کو رہائش کے لئے زمین دے دی گئی تاکہ وہ بات پوری ہو.جو خدا تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ ہم نے اس مقام کو مثابہ بنایا ہے.پس وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں بات کو پورا کرنے کی کیوں کوشش کی وہ درحقیقت کلامِ الٰہی کی حقیقت سے آگاہ نہیں.خدا تعالیٰ کے بندوں کا سب سے بڑا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اُن باتوں کو پورا کرنے کے لئے اپنی طرف سے انتہائی کوشش کریں جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے خبردی ہو اور کہا ہو کہ ایسا ہو جائے گا.اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی کی مدد کی کیاضرورت ہے تو یہ اعتراض صرف اس پیشگوئی پر ہی نہیں پڑے گا بلکہ ہر بات پر پڑےگا.خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے.وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ(الذاریات:۵۷) یعنی میں نے جنّ وانس کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے.اب اگر خدا تعالیٰ کی بات پوری کرنے کے لئے کوئی تدبیر کرنا جائز نہیں تو لوگوں کو نمازوں کی تلقین بھی چھوڑ دینی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خود لوگوں سے نمازیں پڑھوالیگا ہم اس کے لئے کیوں کوشش کریں.اسی طرح فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (الحجر:۱۰)یعنی ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریںگے.اب اگر یہ درست ہے کہ خدائی وعدوں کو پورا کرنے کے لئے کوشش نہیں کرنی چاہیے تو قرآن کریم کا حفظ کرنا بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کی بے حرمتی ہے.اسی طرح قرآن کریم کا چھاپنا بھی بند کر دینا چاہیے کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کریںگے پھر ہم اسے کیوں چھاپیں.غرض یہ ایک احمقانہ خیال ہے جسے کوئی معقول انسان تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا.بہر حال اس آیت سے یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کوئی بات کہے تو مومنوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اُسے پورا کرنے کے لئے ہر قسم کی تدابیر اور کوشش سے کام لیں اور اُس وقت تک صبر نہ کریں جب تک کہ خدا تعالیٰ کی بات پوری نہ ہو جائے.دوسرا امر ا س سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو ہمیشہ الہٰی منشاء کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ لَا یَنَالُ عَھْدِی الظّٰلِمِیْنَ.یعنی تیری اولاد میں کچھ ظالم لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں جن سے میرا کوئی عہد نہیں ہو گا.حضرت ابراہیم علیہ السلام کی احتیاط دیکھو کہ انہوں نے فوراً اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا اور جب مکّہ والوں کے لئے دُعا کی تو عرض کیا کہ وَارْزُقْ اَھْلَہٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْھُمْ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ یعنی اے خدا جو لوگ ان میں سے اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لائیں تو اپنے فضل سے انہیں ہر قسم کے پھل عطا فرما گویا لَا یَنَالُ عَھْدِی الظّٰلِمِیْنَ کی آواز سُنتے ہی انہوں نے
Page 464
منکرین توحید کو اپنی دعا سے خارج کر دیا اور صرف اُن لوگوں تک اپنی دعا کو محدود کر دیا جو خدااور یومِ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں اور دُعا یہ کی کہ وَارْزُقْ اَھْلَہٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ یعنی اے خدا میں تجھ سے ان کے لئے جمعرات کی روٹی نہیں مانگتا.َمیں تجھ سے اُن کے لئے چاول نہیں مانگتا.میں تجھ سے ان کے لئے زردہ اور پلائو نہیں مانگتا بلکہ میںیہ مانگتا ہوں کہ یہ جگہ جہاں گھاس کی ایک پتی بھی پیدا نہیں ہوتی اس جگہ دنیا بھر کے میوے آئیں اور یہ اُن میووں کو یہاں بیٹھ کر کھائیں.تو روٹی دیگا تو میں نہیں مانوں گا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دیا.تو زردہ اور پلائو کھلائےگا تو میں نہیں مانونگا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دیا ہے.میں تیری خدائی کا ثبوت تب مانوں گا جب یہ مکّہ میں بیٹھ کر چین اور جاپان اور یورپ اور امریکہ کے میوے کھائیں تب میں تسلیم کرونگا کہ تو نے اپنی خدائی کا ثبوت دے دیاہے میں نے بندہ ہو کر ایک انتہائی قربانی کی ہے.اب اے خدا میں تیری خدائی کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ بھی اس رنگ میں کہ اس وادیءِ غیر ذی زرع میں دنیا کا ہر بہترین پھل تو انہیں پہنچا.خدا تعالیٰ نے ابراہیم ؑ کے اس چیلنج کو قبول کیا.اور اس نے کہا اے ابراہیم ؑ ! تو نے اپنی اولاد کو ایک وادی غیر ذی زرع میں لا کر بسایا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ میں نے اپنا بیٹا قربان کردیا ہے اب تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے.تُو نے کہا ہے کہ میں نے ایک عاجز بندہ ہو کر اپنی بندگی کا ثبوت دیا.اب اے خدا تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے.اور تو نے ثبوت یہ مانگا ہے کہ یہ نہ کمائیں بلکہ بنی نوع انسان کمائیں اور انہیں کھلائیں.اور کھلائیں بھی معمولی چیزیں نہیں بلکہ دنیا بھر کے میوے ان کے پاس پہنچیں.میں تیرے اس چیلنچ کو قبول کرتا ہوں اور میں اس وادی غیرذی زرع میں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اُگتی تجھے ایسا ہی کر کے دکھائوںگا.میں نے حج کے موقعہ پر خود اس کا تجربہ کیا ہے میں نے مکّہ مکرمہ میں ہندوستان کے گنّےدیکھے ہیں.میں نے مکّہ مکرمہ میں طائف کے انگور کھائے ہیں.میں نے مکہ مکرمہ میں اعلیٰ درجہ کے انار کھائے ہیں.گنّے کے متعلق تو مجھے یاد نہیں کہ میری طبیعت پر اس کے متعلق کیا اثر تھا لیکن انگوروں اور اناروں کے متعلق میں شہادت دے سکتا ہوں کہ ویسے اعلیٰ درجہ کے انگور اور انار میں نے اور کہیں نہیں کھائے.میں یورپ بھی گیا ہوں.میں شام بھی گیا ہوں.میں فلسطین بھی گیا ہوں.اٹلی کا ملک انگوروں کے لئے بہت مشہور ہے.یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ بہترین انگور اٹلی میں ہوتے ہیں.مگر میں نے اٹلی کے لوگوں سے کہا کہ مکّہ کی وادی غیر ذی زرع میں ابراہیمی پیشگوئی کے ماتحت جو انگور میں نے کھائے ہیں وہ اٹلی کے انگوروں سے بہت زیادہ میٹھے اور بہت زیادہ لذیذ تھے.ہمارے اردگرد قندھار، کوئٹہ اور کابل کا انار مشہور ہے.مگر میں نے جو موٹا سُرخ شیریں اور لذیذ انار مکّہ میں کھایا ہے اس کا سینکڑواں حصّہ بھی قندھار اور کوئٹہ اور کابل کا انار نہیں.غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا.
Page 465
اے خدا میں نے اپنی بندگی کا انتہائی ثبوت دےدیا ہے.اب تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی اپنی خدائی کا ثبوت دے اور وہ ثبوت میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ یہ نہ کمائیں بلکہ لوگ کما کر ان کے پاس لائیں اور لائیں بھی معمولی چیزیں نہیں بلکہ دنیا بھر کے بہترین پھل اور میوے.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَارْزُقْ اَھْلَہٗ مِنَ الثَّمَرٰتِکی دُعا مانگ کر درحقیقت مکّہ والوں کے لئے انتہا درجہ کے ترفّہ کے لئے دعا کر دی.کیونکہ مکّہ میں ثمرات کا مہیا ہونا ناممکن تھا.وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی.اور پھلوں کا دُور سے آنا ناممکن تھا.کیونکہ ثمرات کا تازہ بتازہ اور عمدہ ہونا ضروری ہوتا ہے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا کی کہ الٰہی یہ لوگ ان چیزوں سے بھی محروم نہ ہوں تاکہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم اِن ثمرات سے اس وجہ سے محروم ہیں کہ ہم دنیا سے کٹ کر صرف اس گھر کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں.پس ایسی نازک اشیاء بھی یہاں پہنچ جائیں تاکہ دنیا پر حجت ہو کہ خدا تعالیٰ نے جنگل میں منگل کر دیا.چنانچہ اس ابراہیمی دعا کی برکت سے ہر قسم کا تازہ بتازہ پھل مکہ والوں کو میسر آرہا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے خود حج کے موقعہ پر مکہ مکرمہ میں نہایت شیریں انار دیکھے ہیں اور انگور ایسے اعلیٰ درجہ کے کھائے ہیں کہ اٹلی اور فرانس کا انگور اس کے مقابلہ میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کابلی انگور کے مقابلہ پر پنچابی انگور.غرضیکہ تمام اعلیٰ درجہ کی چیزیں مکّہ میں میّسرآجاتی ہیں.ایک دفعہ حج کے موقعہ پر گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بزرگ نے خواہش کی کہ اگر برف ہوتی تو میں ستّو پیتا.چنانچہ انہوں نے دعا کی کہ الٰہی یہ تیراگھر ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ میں یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کا رزق عطا کروں گا.سو تو اپنے فضل سے میرے لئے برف مہیا فرما دے.خدا تعالیٰ نے اولے برسا دیئے جو لوگوں نے جمع کر لئے اور انہوں نے برف ڈال کر ستّو پیئے.غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جو لوگ یہاں رہیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ یہ خیال کریں کہ ہم خدا تعالیٰ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے ان نعمتوں سے جو دوسروں کو میّسر ہیں محروم ہو گئے ہیں اس لئے اے خدا تو انہیں ہرقسم کے اعلیٰ درجہ کے پھل کھلا.اور انہیں اپنے انعامات سے متمتع فرماتاکہ ان کو یہ نظر نہ آئے کہ ہم اس گھر کے لئے قربانیاں کر رہے ہیں بلکہ یہ نظر آئے کہ ہمیں خدا تعالیٰ اپنے انعامات سے حصہ دے رہا ہے.یہاں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے آرام کے لئے دعائیں مانگی ہیں لیکن درحقیقت انہوں نے خدا تعالیٰ کی غیرت بھڑکا نے کے لئے یہ دعائیں کی ہیں چونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ طَهِّرَا بَيْتِيَ.اس لئے ان کے دل میں خیال آیا کہ آئندہ آنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں اور ایک بے آب و گیاہ جگہ میں آکرخدا تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ محسوس کریں کہ خدا تعالیٰ ہم پر احسان کر رہا ہے.اس لئے
Page 466
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت احتیاط سے دعا کی اور کہا کہ الہٰی تو صرف اُن کو ثمرات عطا فرما جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں.غالباً آپ کا منشاء یہ ہو گا کہ دوسرے لوگ بھوک وغیرہ سے تنگ آکر خود ہی مکّہ سے نکل جائیں اور اس طرح یہ مقام ہمیشہ کے لئے خدا تعالیٰ کے پاک بندوں سے آباد رہے.مگر اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملہ میں اس تخصیص کو پسند نہ فرمایا.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مِنَ الثَّمَرٰتِ کیوں کہا؟ آخر میووں سے تو کوئی نہیں جیتا.روٹی سے انسان زندہ رہتا ہے مگر انہوں نے روٹی نہیں مانگی بلکہ پھل مانگا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ مکّہ وہ مقام ہے جہاں کوئی چیز پیداہی نہیں ہوتی تھی اور باہر سے بھی سخت چیزیں تو وہاں پہنچ جاتی تھیں لیکن نازک چیزیں وہاں پہنچتے پہنچتے گل سڑ جاتی تھیں.پس انہوں نے روٹی مانگنے کی بجائے پھل مانگے جو ایک نہایت نازک چیز ہے اور سمجھا کہ جب میوے آجائیںگے تو اور چیزیں تو خود بخود آجائیں گی.چنانچہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے وہاں ہر ملک کے میوے ملتے ہیں.پس میوے ملنے سے مراد یہ ہے کہ انکو میوے بھی مل جائیں اور باقی اشیاء بھی مل جائیں.گویا میووں میں ہی باقی اشیاء کا ذکر آجاتا ہے.قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کے معاملہ میں ہمارا اَور حکم ہے اور نبوت اور امامت کے معاملہ میںاَور حکم ہے.نبوت اور امامت صرف نیک لوگوں کو ملتی ہے مگر رزق ہر ایک کو ملتا ہے پس جو کافر ہو گا دنیا کی روزی ہم اس کو بھی دیں گے چنانچہ سینکڑوں سال تک مکّہ کے لوگ مشرک رہے مگر خدائی رزق ان کو بھی پہنچتا رہا ہاں تیری نسل ہونے کی وجہ سے وہ اُخروی عذاب سے نہیں بچ سکتے.مر جائیں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے.اس جگہ اُمَتِّعُہٗ قَلِیْلًا سے صرف چند دنوں کا رزق مراد نہیں بلکہ اس سے دنیوی نفع مراد ہے جو مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیْلٌ کا مصداق ہوتا ہے.مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ میں یا تو فاء زائدہ ہے یا مَنْ کی خبر محذوف ہے اور اصل عبارت یوں ہے کہ اَرْزُقُہٗ فَاُمَتِّعُہٗ یعنی میں اُسے رزق بھی دوں گا اور اس کے علاوہ ہر قسم کی دوسری منفعت بھی اُسے پہنچتی رہے گی.مگر روحانی فوائد جب تک کوئی شخص انبیاء سے تعلق نہیں رکھے گا اُسے نہیں ملیں گے.گویا اس جگہ فاء عطف کے لئے ہے.تورات میں اس دعا کا کہیں ذکر نہیں آتا کیونکہ یہود نے بنو اسمٰعیل کی دشمنی کی وجہ سے تورات سے مکّہ کا ذکر ہی اُڑا دیا ہے.البتہ خانہ کعبہ کا ذکر اُس میں بعض جگہ مل جاتا ہے.
Page 467
اِس آیت سے یہ استدلال بھی ہوتا ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بڑا زور دیا کرتے تھے.کہ انبیاء کے انکار کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا بلکہ عذاب محض شرارت اور فساد کی وجہ سے آتا.اگر لوگ تقویٰ کی زندگی بسر کریں تو محض انبیاء کے انکار کی وجہ سے اس دنیا میں اُن پر عذاب نہیں آسکتا.اصل بات یہ ہے کہ انسان جسم و رُوح سے مرکب ہے وہ جسمانی اطاعت کے ساتھ جسمانی دنیا میں سکھ پا لیتا ہے.لیکن جب خالص روحانی دنیا آتی ہے تو چونکہ اس نے اس زندگی کا کام نہیں کیا ہوتا اس لئے وہاں اُسے تکلیف پہنچتی ہے مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں امن قائم کرنے کا یہ نہایت ہی اعلیٰ درجے کا ذریعہ بتایا ہے کہ اختلاف مذہب دنیوی تعلقات کو توڑ دینے کا موجب نہیں ہونا چاہیے.اگر دنیا اس پر عمل کرے اور فتنہ و فساد میں حصہ نہ لے تو تمام مذہبی جھگڑے اور فسادات مٹ سکتے ہیں.ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا سے مراد کچھ دن نہیں بلکہ دنیوی زندگی ہے کیونکہ یہاں فرماتا ہے میں انہیں مضطر کرکے عذاب کی طرف لے جائوں گا.اور عذاب کی طرف انسان موت کے بعد ہی جا سکتا ہے.بہر حال خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور کوئی جگہ انکی پناہ کے لئے نہیں رہے گی.وہ ایک ہی جگہ لیجائے جائیں گے اور وہ عذاب کی جگہ ہو گی اور وہ بہت بُرا ٹھکانہ ہے.گھیر گھار کر اور مجبور کر کے لے جانا اپنے اندر ایک حکمت رکھتا ہے.بظاہر اس کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجبور کر کے عذاب کی طرف لے جاتا ہے.لیکن اس سے یہ مراد نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب انسان متواتر کوئی بُرا کام کرتا ہے تو اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر اس کی نیکی کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں.اور وہ بدیوں کی طرف کھچا چلا جاتا ہے.جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے وہ کہا کرتے ہیں کہ نیکی کا کیا ہے وہ تو ہم جب چاہیں کر سکتے ہیں حالانکہ یہ درست نہیں.قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ گناہ کوئی مفرد چیز نہیں بلکہ وہ ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک بیج درخت پیدا کر دیتا ہے اور پھر اس سے آگے اور درخت پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح ہر گناہ اپنے ظہور کے بعد اور گناہ پیدا کرتا ہے.یہی حال نیکی کا ہے.ہر نیکی اپنے ظہور کے بعد اور نیکیاں پیدا کرتی ہے.خدا تعالیٰ کا رحیم ہونا نیکیوں کے بڑھانے پر دلالت کرتا ہے اور اس کا قہار ہونا بدیوں کے بڑھانے پر دلالت کرتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ انسان کو بدی پر مجبور کرتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ متواتر بدیوں کے نتیجہ میں انسان اپنے آپ کو ایسے مقام پر پاتا ہے جس سے اگر وہ بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا.پس اَضْطَرُّہٗ میں انسان کو مایوس کرنا مراد نہیں بلکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو بدیوں سے بچ کر رہنا چاہیے.ورنہ اس پر ایسی حالت
Page 468
طاری ہو جائیگی کہ وہ بدیوں کی طرف کھینچا چلا جائےگا اور اس کا پیچھے قدم ہٹا نا مشکل ہو جائے گا.کیونکہ جب انسان کسی بدی میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے لئے چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے.پس اس میں کسی جبر کی طرف اشارہ نہیں بلکہ احتیاط کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے.چنانچہ آگے فرماتا ہے وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ.اگرمجبور کرنا مراد ہوتا ہے تو بِئْسَ الْمَصِیْرُکہنے کا کوئی مطلب نہیں تھا.یہ الفاظ اس لئے لائے گئے ہیں کہ انسان کو توجہ دلائی جائے کہ اُسے اس بارہ میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے اور بدی کے ارتکاب سے بچنا چاہئے ورنہ اس کے اندر بدی کے لئے ایک اضطرار کی سی کیفیت پیداہو جائے گی.یہی حالت انسان کے دوسرے افعال میں بھی پائی جاتی ہے.چنانچہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی بعض دفعہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں.جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی حرکت چند بار کی اور پھر انہیں اس کی عادت پڑگئی.اسی طرح نیکی اور بدی دونوں کی ابتداء انسان کے اپنے اختیار سے ہوتی ہے مگر انتہاء اضطرار پرہوتی ہے.اور چونکہ ابتداء انسان کے اختیار سے ہوتی ہے اس لئے اس کی انتہاء بھی اختیار کے تابع سمجھی جاتی ہے.مثلاً جس انسان کو نماز کی پرانی عادت ہو اسے نماز کا ثواب برابر ملتا چلا جاتا ہے.کیونکہ اس نے ارادہ سے اس کی ابتداء کی ہوتی ہے.یہی حال بدی کا ہوتاہے انسان اُسے اپنے اختیار سے شروع کرتا ہے لیکن آخر میں اضطرار تک حالت پہنچ جاتی ہے اور پھر اگر وہ اس سے بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا اور وہ اس بدی کا غلام بن جاتا ہے.اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ یہ لوگ ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اپنے آپ کو بدی کرنے پر مجبور پاتے تھے.اس لئے خدابھی انہیں مجبور کر کے دوزخ کی طرف لے جائے گا اور انہیں اپنے عمل کے مطابق بدلہ مل جائےگا.وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ١ؕ اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب ابراہیم ؑ اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور (اس کے ساتھ) اسمٰعیل بھی ( اور وہ دونوں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۰۰۱۲۸ کہتے جاتے تھے کہ) اے ہمارے رب ! ہماری طرف سے ( اس خدمت کو) قبول فرما.تو ہی (ہے جو) بہت سننے والا (اور) بہت جاننے والا ہے.تفسیر.اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بیت اللہ کو ہم نے مثابہ اور امن کا مقام بنایا ہے.اس
Page 469
میں یہ کوئی ذکر نہیں تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کس کے ہاتھوں ہوئی.مگر اب فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیادیں کھڑی کیں.اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی تھیں.مگر یہ درست نہیں.کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یَضَعُ الْقَوَاعِدَ نہیں فرمایا بلکہ یَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ فرمایا ہے.اگربنیاد رکھنے کا ذکر ہوتا تو وَضَعَ کا لفظ استعمال کیا جاتا.اس سے معلوم ہوتا ہے.کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا مگر اس کی عمارت منہدم ہو چکی تھی.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اس کی بنیادوں کو بلند کیا.اور بیت اللہ کی ازسرِ نو تعمیر کی.قرآن کریم کی بعض اور آیات سے بھی اس مضمون کی تصدیق ہوتی ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے.اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ (اٰلِ عمران:۹۷) یعنی سب سے پہلا گھر جو تمام لوگوں کے فائدہ کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو مکّہ مکرمہ میں ہے.وہ تمام جہانوں کے لئے برکت والا اور ہدایت کا مقام ہے.اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعائیں کیں اس کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ(ابراہیم :۳۸)یعنی اے ہمارے رب! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے معزز گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی.یہ دُعا بھی بتاتی ہے کہ بیت اللہ وہاں پہلے سے موجود تھا کیونکہ یہ دعا اس وقت کی ہے جب حضرت اسمٰعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسمٰعیل کو وہاں لا کر بسادیا تھا.اُس وقت وہ دعامیں عِنْدَ بَيْتِكَ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جگہ اُنکو الہاماً بتائی گئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ پہلا گھر ہے جو خدا تعالیٰ کے لئے تعمیر ہوا.اسی طرح قرآن کریم نے ایک مقام پر بیت اللہ کو بَیْتُ الْعَتِیْقِ بھی قرار دیا ہے چنانچہ فرماتا ہے.وَ لْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ(الحج :۳۰)یعنی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس قدیم ترین گھر کا طواف کریں.اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ بہت پرانا گھر ہے یا یوں کہو کہ وہ پہلی عبادت گاہ ہے جو دُنیا میں تیار کی گئی.پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی نہیں بلکہ انہوں نے صرف اس کی عمارت کی تجدید کی تھی اور اس کی اصلی بنیادوں پر اُسے کھڑا کیا تھا.احادیث سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بیت اللہ کے نشانات موجود تھے.چنانچہ بخاری میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اسمٰعیل کو وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو فَقَالَتْ: یَا اِبْرَاھِیْمُ اَیْنَ تَذْ ھَبُ وَ تَتْرُکُنَا بِھٰذَالْوَادِی الَّذِیْ لَیْسَ فِیْہِ اَنِیْسٌ وَ لَا شَیْءٌ ؟ فَقَالَتْ لَہٗ ذٰلِکَ مِرَارًا وَجَعَلَ لَایَلْتَفِتُ اِلَیْھَا فَقَالَتْ لَہٗ : آاَللّٰہُ اَمَرَکَ بِھٰذَا؟ قَالَ نَعَمْ! قَالَتْ اِذًا لَا
Page 470
یُضَیِّعُنَا.ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ اِبْرَاھِیْمُ حَتّٰی اِذَا کَانَ عِنْدَ الثَّنِیَّۃِ حَیْثُ لَا یَرَوْنَہٗ اِسْتَقْبَلَ بِوَجْھِہِ الْبَیْتَ ثُمَّ دَعَا بِھٰؤُلَٓاءِ الْدَّعْوَاتِ وَرَفَعَ یَدَیْہِ فَقَالَ، رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّ یَّـــتِیْ بِوَادٍ غَیْرِ ذِیْ زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ(بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب یزفون النسلان فی المشی )یعنی حضرت ہاجرہؓ نے کہا.اے ابراہیم! تم کہاں جا رہے ہو.کیا تم ہمیں ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ کوئی انسان ہے اورنہ کوئی اَور چیز.اور انہوں نے بار بار یہ سوال کیا.مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام شدّتِ رقت کی وجہ سے جو اُن پر طاری تھی اس کا جواب نہ دے سکے بلکہ اُن کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے اس پر حضرت ہاجرہؓ نے کہا.بتائیں کیا خدا نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا.ہاں! تب حضرت ہاجرہؓ نے کہا.کہ پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں.خدا تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا.یہ کہہ کر وہ واپس چلی آئیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام موڑ پر پہنچے اور ہاجرہ ؓ اور اسمٰعیل ؑ اُن کی نظر سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا (اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کا نشان موجود تھا گو عمارت نہیں تھی )اور ہاتھ اُٹھا کہ یہ دُعا کی کہ رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ١ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ.(ابراہیم :۳۸ ) یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے صرف اس کی عمارت کی تجدید کی تھی.اور یہ کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے اور اس کی ابتداء ایسے زمانہ سے وابستہ ہے جس کا علم صرف خدا تعالیٰ کو ہی ہو سکتا ہے.تاریخ اس کو بیان نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کی طرف منہ کر کے خاص طور پر دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور رحم طلب کیا.میور جیسا متعصّب مصنّف بھی اپنی تصنیف ’’لائف آف محمد ‘‘ میں تسلیم کرتا ہے کہ.’’مکّہ کے مذہب کے بڑے بڑے اصولوںکو ایک نہایت ہی قدیم زمانہ کی طرف منسوب کرنا پڑتا ہے.گو ہیروڈوس(مشہور یونانی جغرافیہ نویس) نے نام لے کر کعبہ کا ذکر نہیں کیا مگر وہ عربوں کے بڑے دیوتائوں میں سے ایک دیوتا اللَّات(یعنی خدائوں کا خدا) کا ذکر کرتا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مکّہ میں ایک ایسی ہستی کی پرستش کی جاتی تھی جسے بڑے بڑے بتوں کا بھی خدا مانا جاتا تھا.‘‘(�) پھر لکھتا ہے کہ مشہور مؤرخ ڈایوڈواس سکولس جو ساٹھ سال قبل مسیح گذرا ہے اُس نے بھی کہا ہے کہ
Page 471
عرب کا وہ حصّہ جو بحیرہ احمر کے کنارے ہے وہاں پتھر کا ایک معبد بنا ہوا ہے جو بہت قدیم زمانہ سے ہے اور جس کی طرف عرب کے چاروں اطراف سے گروہ در گروہ لوگ آتے رہتے ہیں.سر ولیم میور اس کا ذکر کرتا ہوا لکھتا ہے کہ یہ الفاظ مکّہ کے مقدّس گھر کے متعلق ہی ہیں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں جس نے اتنا بڑا احترام حاصل کیا ہو.(دیباچہ لائف آف محمد�) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ یہ انبیاء ہی کی شان ہے کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں.لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو فخر کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں.مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں.پھر وہ بڑا ہوتا ہے تو اسے ایک ایسے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں جہاں نہ کھانے کا کوئی سامان تھا نہ پینے کا.اور پھر خانہ کعبہ کی عمارت بنا کر اُن کی دائمی موت کو قبول کر لیتے ہیں.دائمی موت کے الفاظ میں نے اس لئے استعمال کئے ہیں کہ ممکن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واپس آجانے کے بعد وہ وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلے جاتے.مگر بیت اللہ کی تعمیر کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کے ساتھ باندھ دیئے گئے گویا خانہ کعبہ کی ہر اینٹ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کو بزبان حال کہہ رہی تھی کہ تم نے اب اسی جنگل میں اپنی تمام عمر گزارنا ہے.یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمٰعیل علیہ السلام نے کی.مگر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے اور کہتے ہیں کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا.اے اللہ! ہم ایک حقیر ہدیہ تیرے حضور لائے ہیں تو اپنے فضل سے چشم پوشی فرما کر اسے قبول فرما لے.اور پھر کتنے تکلّف سے قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں.تَقَبَّلْ باب تفعّل سے ہے اور تفعّل میں تکلّف کے معنے پائے جاتے ہیں.پس وہ کہتے ہیں کہ تو خود ہی رحم کر کے اس قربانی کو قبول فرمالے حالانکہ یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی.باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو قربان کر رہا تھا اور خانہ کعبہ کی ہر اینٹ ان کو بے آب و گیاہ جنگل کے ساتھ مقیّد کر رہی تھی.خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ایک ایک اینٹ کے ساتھ ان کے جذبات و احساسات کو دفن کر رہے تھے مگر دعا یہ کرتے ہیں کہ الہٰی یہ چیز تیرے حضور پیش کرنے کے قابل تو نہیں مگر تو ہی اسے قبول فرما لے.یہ کتنا بڑا تذلّل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا اور درحقیقت قلب کی یہی کیفیت ہے جو انسان کو اونچا کرتی ہے.ورنہ اینٹیں تو ہر شخص لگا سکتا ہے مگر ابراہیمی دل ہو تب وہ نعمت میّسر آتی ہے جو خدا تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی.پس ہر انسان کو چاہیے کہ وہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ کہے.لیکن افسوس ہے کہ لوگ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا کہنے کی بجائے یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری قدر نہیں کی جاتی.حالانکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں کی
Page 472
نقل میں کرتے ہیں.لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی نقل میں قربانی نہیں کی.بلکہ اِدھر خدا نے حکم دیا اور اُدھر وہ قربانی کے لئے تیار ہو گئے.یہی وہ لوگ ہیں جو دُنیا کے ستون ہوتے ہیں اور جن کا بابرکت وجود مصائب کے لئے تعویذکا کام دے رہا ہوتا ہے.وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ کہتے جاتے ہیں کہ اے خدا ہماری قربانی اس قابل نہیں کہ تیرے حضور پیش کی جاسکے.تیری ہستی نہایت اعلیٰ و ارفع ہے.ہاں ہم امید رکھتے ہیں کہ تو چشم پوشی سے کام لیتے ہوئے اسے قبول فرمالے گا.تیرا نام سمیع ہے اور تو دعائوں کو سننے والا ہے.ہماری یہ قربانی قبول کرنے کے لائق تو نہیں مگر تو جانتا ہے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ اور کچھ چیز نہیں جو تیرے سامنے پیش کریں.ایک طرف تیرا سمیع ہونا چاہتاہے کہ تو ہم پر رحم کرے اور دوسری طرف تیرا علیم ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تو جانتا ہے کہ ہمارے جیسے نے کیا قربانی کرنی ہے.اسی رُوح کا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمٰعیل علیہ السلام نے مظاہرہ کیا.اور جب وہ دونوںمل کر بیت اللہ کی بنیادیںاُٹھا رہے تھے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے جاتے تھے کہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا.اے ہمارے رب ہم نے خالص تیری توحید اور محبت کے لئے یہ گھر بنایا ہے تو اپنے فضل سے اسے قبول کر لے اور اس کو ہمیشہ اپنے ذکر اور برکت کی جگہ بنا دے.اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ تُو ہماری درد مندانہ دعائوں کو سننے والا اورہمارے حالات کو خوب جاننے والا ہے.تو اگر فیصلہ کر دے کہ یہ گھر ہمیشہ تیرے ذکر کے لئے مخصوص رہے گا تو اسے کون بدل سکتا ہے.اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بیت اللہ بنا نے کے درحقیقت دو۲ حصّے ہیں.ایک حصہ بندے سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا حصہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے جس مکان کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں وہ اینٹوں سے بنتا ہے.چُونے سے بنتا ہے گارے سے بنتا ہے اور یہ کام خدا نہیں کرتا بلکہ انسان کرتا ہے.مگر کیا انسان کے بنانے سے کوئی مکان بیت اللہ بن سکتا ہے.انسان تو صرف ڈھانچہ بناتا ہے روح اس میں خدا تعالیٰ ڈالتا ہے.اسی امر کو مدِّنظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ڈھانچہ تو میں نے اور اسمٰعیل ؑ نے بنا دیا ہے مگر ہمارے بنانے سے کیا بنتا ہے.کئی مسجدیں ایسی ہیں جو بادشاہوں اور شہزادوں نے بنائیں مگر آج وہ ویران پڑی ہیں.اس لئے کہ انسان نے تو مسجدیں بنائیں مگر خدا نے انہیں قبول نہ کیا.پس حضرت ابراہیم ؑ اور حضرت اسمٰعیل ؑ کہتے ہیں کہ اے خدا! ہم نے تیراگھر بنایا ہے اسے تو قبول فرما.اور تو سچ مچ اس میں رہ پڑ.اور جب خدا کسی جگہ بس جائے تو وہ کیسے اُجڑ سکتا ہے.گائوں اُجڑ جائیں تو اُجڑ جائیں شہر اُجڑ جائیں تو اُجڑ جائیں مگر وہ مقام کبھی اُجڑ نہیں سکتا جس جگہ خدا بس گیا ہو.
Page 473
رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً اے ہمارے رب ! اور( ہم یہ بھی التجاء کرتے ہیں کہ )ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار (بندہ) بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی لَّكَ١۪ وَ اَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا١ۚ اِنَّكَ اَنْتَ اپنی ایک فرمانبردار جماعت (بنا) اور ہمیں ہمارے (مناسب حال) عبادت کے طریق بتا اور ہماری طرف (اپنے ) فضل کے التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۰۰۱۲۹ ساتھ توجہ فرما.یقیناً تو (اپنے بندوں کی طرف) بہت توجہ کرنے والا (اور) باربار رحم کرنے والا ہے.حَلّ لُغَات.مُسْلِمٌ : فرمانبردار کو کہتے ہیں.(اقرب) اُمَّۃٌ :کے معنے جماعت کے ہوتے ہیں.(اقرب) اَرِنَا: ہمیں دکھادے.رُؤْیَۃ آنکھوں کی بھی ہوتی ہے اور دل کی بھی.یہاں دونوں ہی مراد ہو سکتی ہیں.مگر آگے چونکہ مَنَاسِک کا لفظآیا ہے اس لئے بجائے دکھادے کے ہم یوں کہیں گے ہم پر ظاہر کر دے یا ہمیں بتا دے.مَنَاسِکُ: مَنْسَکٌ کی جمع جس کے معنے عبادت کے ہوتے ہیں.یا وہ تمام حقوق جو خدا تعالیٰ کے حضور ہمیں ادا کرنے چاہئیں.(اقرب) تَوْبَۃ: جب یہ لفظ بندہ کے لئے آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں بندہ کا خدا تعالیٰ کی طرف سچے دل سے جھکنا اور اس کی طرف رجوع کرنا.اور جب یہ خدا تعالیٰ کے لئے آئے تو اس کے معنے ہوتے ہیں.خدا تعالیٰ کا بندوں پر رحم کرنا.اس میں اور رحم میں یہ فرق ہے کہ رحیم کا لفظ نیکی کے بعد روحانی ترقیات دینے پر دلالت کرتا ہے اور توبہ کا لفظ اُن ترقیات پر دلالت کرتا ہے جو نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہ پہنچیں بلکہ اس سے نیچے رہیں.تَوَّاب زیادہ تر بدیوں اور کمزوریوں کے دور کرنے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے اور روحانی قابلیتوں اور طاقتوں کے پیدا کرنے کے موقع پر رحیم کا لفظ آتاہے یہ دونوں الگ الگ قسم کی رحمت ہے.رحیم ارتقاء اور زیادتی کے لئے اور توّاب نقصان سے پاک ہو نے کے لئے آتا ہے.گویا جب انسان نقصان سے پاک ہو جاتا ہے اور روحانی ارتقاء کی طرف مائل ہو جاتا
Page 474
ہے تو صفت رحیمیّت کادور دورہ ہو جاتا ہے.تفسیر.پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے فرماتے ہیں.اے خدا! اس گھر کی آبادی تیرے بندوں سے وابستہ ہے.مگر محض لوگوں کی آبادی کوئی چیز نہیں.اصل چیز یہ ہے کہ اس سے تعلق رکھنے والے نیک ہوں.پس ہم جو بیت اللہ کو بنانے والے ہیں اور جو دو۲ افراد ہیںہماری پہلی دُعا تو یہ ہے کہ تو خود ہمیں نیک بنا وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ اور پھر ہماری اولاد میں سے ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے جو تیرا مطیع اور فرمانبردار ہو.وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور ہمارے مناسب حال ہمیں عبادت کے طریق بتا.اصل بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں خواہ کتنا ہی اخلاص ہو.اگر اسے طریق معلوم نہ ہو کہ کس طرح کسی گھر کو آباد رکھنا ہے تو پھر بھی وہ غلطی کر سکتا ہے.اس لئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا نہ صرف ہمارے دلوں میں ایمان قائم رکھ بلکہ وقتاً فوقتاً ہمیں یہ بھی بتاتا رہیو کہ ہم نے کس طرح اسے آباد رکھنا ہے اور ہم وہ کونسا طریق عبادت اختیار کریں جس سے تو خوش ہو اور یہ گھر آباد رہ سکے.اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اَرِنَا الْمَنَا سِکَ کہنے کی بجائے مَنَاسِکَنَا کہا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانہ کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور کامل مومن وہی ہوتا ہے جو ان فرائض کو سمجھنے کی کوشش کرے جو بدلے ہوئے حالات کے مطابق اُس پر عائد ہوتے ہیں محض ایک پرانی لکیر پر چلتے چلے جانا اور حالات کے تغیّر کو مدّنظر نہ رکھنا انسان کو کسی ثواب کا مستحق نہیں بناتا.افسوس ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں نے بھی اس نکتہ کو نہ سمجھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاد بالسیف پر ہی زور دیتے رہے حالانکہ زمانہ اُن سے تلوار کے جہاد کا نہیں بلکہ زبان اور قلم کے جہاد کا مطالبہ کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دُعا کرتے ہیں کہ الٰہی جو نیکی جس وقت کے مناسب حال ہو اس کو سرانجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس بارہ میں ہمیشہ ہماری رہنمائی فرما.حدیثوں میں آتا ہے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! سب سے بڑی نیکی کون سی ہے.آپؐ نے فرمایا سب سے بڑی نیکی تہجد ہے.پھر کسی اور نے آپؐ سے پوچھا کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے.توآپؐ نے فرمایا جہاد سب سے بڑی نیکی ہے.اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص کے لئے الگ الگ بڑی نیکیاں ہیں.جوشخص جہاد نہیں کرتا اس کے لئے جہاد ہی سب سے بڑی نیکی ہے اور جو شخص کبرونخوت سے بھرا ہوا ہو اس کے لئے سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ وہ کبر ونخوت چھوڑ دے.جو شخص نیند کا متوالا ہے او ر اس وجہ سے عشاء اور صبح کی نمازیں مسجد میں ادا نہیں کر سکتا.اس کے لئے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ نیند دور کرے.اور
Page 475
نمازیں مسجد میں ادا کرے.جو شخص تہجد نہیں پڑھتا اس کے لئے سب سے بڑی نیکی تہجد پڑھنا ہے.جو شخص ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا.اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے.غرض نیکی کا جو کام کسی کے نفس پر بوجھل ہو وہی اس کے لئے سب سے بڑی نیکی ہے اسی طرح جس چیز کی ضرورت دوسروں پر مقدم سمجھی جائے وہی سب سے بڑی نیکی ہے نماز کے وقت نماز ہی سب سے بڑی نیکی ہے.اور روزہ کے وقت روزہ ہی سب سے بڑی نیکی ہے.غرض انسان کے لئے مختلف اوقات میں مختلف بڑی نیکیاں ہوتی ہیں اسی طرح مختلف اقوام اور افراد اور زمانوں کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی نیکی کی تعیین مختلف ہوتی چلی جاتی ہے جس قوم یا جس فرد یا جس زمانہ کے لئے جس نیکی کی ضرورت ہو وہی اس کے لئے بڑی بن جاتی ہے اور اس پر عمل اُسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مستحق بنا دیتا ہے.حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی نکتہ کو مدّنظر رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ الٰہی ہم کمزور اور ناطاقت ہیں اور ہم پوری طرح تیری عبادت بجا لانے سے قاصر ہیں تو آپ ہم پر رحم کیجیئو اور ہمارے مناسب حال عبادت کے طریق بتائیو.ہم سے یہ بوجھ نہیں اُٹھایا جاتا.وَتُبْ عَلَیْنَا.مگر اس الہام کے باوجود جو یہ بتاتا رہے کہ کس طرح اس گھر کو آباد رکھنا چاہیے اے خدا! ہم تیرے بندے ہیں ہم نے غلطیاں بھی کرنی ہیں اس لئے تو ہمیں معاف کر دیا کر.اور ہمارے گناہوں سے درگذر کرتا رہ.اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے.توّاب اور رحیم نام اس لئے لائے گئے ہیں کہ بندہ خواہ کتنی بھی نیک نیتی کے ساتھ کام کرے وہ غلطی کر جاتا ہے.ایسی حالت میں توّابیّت اُس کے کام آتی ہے اور اگر اچھا کام کرے تو رحیمیّت اُس کے کام آتی ہے.رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ اور اے ہمارے رب! (ہماری یہ بھی التجا ءہے کہ ) تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُؒ۰۰۱۳۰ سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے یقیناً تو ہی غالب (اور) حکمتوں والا ہے.حَلّ لُغَات.اٰیٰتٌ.اٰیَـۃٌ کالفظ اٰوٰی سے نکلا ہے جس کے معنے ہیں ’’جگہ دی‘‘ (۲) اسی طرح ہر وہ کلام
Page 476
جو لفظی نشان کے ذریعہ ختم کیا جائے آیت کہلاتا ہے.جیسے قرآن کریم کی آیات جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ایک نشان ڈال دیا جاتاہے جو آیت کے ختم ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے.(۳) اس کے ایک معنے عبرت کے بھی ہیں یعنی ایسی بات جو دوسرے کے لئے نصیحت کا باعث ہو(۴)آیت کے معنے کسی چیزکے وجود اور اس کی شخصیت کے بھی ہیں(۵) اس کے ایک معنے جماعت کے بھی ہیں گویا فردی شخصیت بھی اس لفظ کے مفہوم میں آجاتی ہے اور جماعتی شخصیت بھی.چنانچہ کہتے ہیں.خَرَجَ الْقَوْمُ بِاٰ یٰتِھِمْ وَلَمْ یَدَعْ وَرَاءَ ھُمْ شَیْئًا(اقرب)قوم اپنے سارے وجود کو لے کر چلی اور اپنے پیچھے کچھ بھی نہ چھوڑا.بعض نحوی کہتے ہیں کہ آیت کا لفظ تَأْ یّ سے نکلا ہے جس کے معنے تَثَبَّتَ عَلَی الشَّیْ ءِ اور اقامت کے ہیں یعنی کسی چیز کا ٹِک جانا اور ایک جگہ پر جم جانا چونکہ یہ ایک جگہ پر قائم ہوتی ہے اس لئے اسے آیت کہتے ہیں.جیسے سڑکوں پر سنگِ میل ایک علامت اور نشان کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں.(۶) اَ لْاٰیَـۃُ: ھِیَ الْعَـلَامَۃُ الظَّا ھِرَۃُ.اس کے ایک معنے ظاہری علامت کے بھی ہوتے ہیں.یعنی ہر چیز کا جو جسم ہوتا ہے علامت اور آیت کہلاتا ہے مثلاً ایک کتاب کے الفاظ علامت اور آیت کہلاتے ہیں.کیونکہ ان کے ذریعہ مطلب کا پتہ لگتا ہے.غرض ہر وہ چیز جس کے ذریعہ کسی دوسری مخفی چیز کا پتہ لگے وہ آیت ہے.(۷) آیت بناء عالی کو بھی کہتے ہیں.یعنی اونچی عمارت.یہ لفظ اِن معنوں میں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ آتا ہے.اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ (الشعرآء : ۱۲۹)یعنی کیا تم پہاڑوں پر بیفائدہ عمارتیں بناتے ہو.اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پُرانے زمانہ میں یہ عام دستور تھاکہ پہاڑوں پر لوگ عمارتیں بناتے تھے.یہ یورپ کا نیا دستور نہیں.(۸)آیت کے معنے ٹکڑے کے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی آیات ہیں.(۹) آیت عذاب کو بھی کہتے ہیں.جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے.وَمَا نُرْسِلُ بِا لْاٰ یٰتِ اِلَّا تَخْوِیْـفًا.(بنی اسرائیل :۶۰ ) یعنی ہم تو صرف خوف دلانے کیلئے آیات بھیجتے ہیں.(مفردات) اَلْکِتٰبَ.اس کے کئی معنے ہیں.(۱) اَلصَّحِیْفَـۃُ لکھی ہوئی چیز جسے عرف عام میں کتاب کہتے ہیں.(۲)اَلْحُکْمُ.حکم (۳)اَلْفَرْضُ.فرض (۴)جَامِعٌ یعنی جمع کرنے والی چیز.جیسےکَتِیْبَۃٌ ایک بڑے لشکر کو کہتے ہیں.جس میں جھنڈے، سامان اور فوج سب کچھ ہوتا ہے.کتاب کا لفظ اصل میں جوڑنے کے معنے رکھتا ہے.چنانچہ مشکیزہ کا منہ بند کر دینا.یا جانوروں کے منہ میں کوئی آلہ ڈال دینا.جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں یا
Page 477
کھیتوں کو خراب نہ کر سکیں.اُسے کتبہ کہتے ہیں.یہ بھی کتاب کا مصدر ہے.اِسی سے آگے حروف کو دوسرے حروف سے جوڑنے کے معنے پیدا ہو گئے.کتاب کا لفظ لکھی ہوئی چیز کیلئے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے.گو محاورہ میں نہ لکھے ہوئے کلام کو بھی جو کہ معیّن ہو اور یاد کرایا جا تا ہو کتاب کہہ دیتے ہیں.(اقرب)لغت والے اس کی مثال الٓمّٓ ذٰلِکَ الْکِتٰبُ کو پیش کرتے ہیں.وہ کہتے ہیںدیکھو الٓمّٓ کو ذٰلِکَ الْکِتٰب کہا ہے.حالانکہ الٓمّٓ ابھی نازل ہو رہا تھا.اور لکھا ہوا نہ تھا.اِس سے ظاہر ہے کہ غیرمکتوب چیزیں بھی کتاب کہلاتی ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نہ لکھی ہوئی چیز کو بھی کتاب کہہ دیتے ہیں.لیکن لغت والوں کا اس سے یہ استدلال غلط ہے کیونکہ ذٰلِکَ کا اشارہ الٓمّٓ کی طرف نہیں بلکہ اس کا اشارہ سورۃ فاتحہ کی طرف ہے جو پہلے نازل ہو چکی تھی اور لکھی بھی جا چکی تھی.لیکن خواہ اس کا اشارہ الٓمّٓ کی طرف ہو یا ساری سورہ بقرۃ کی طرف ہو یا سارے قرآن کریم کی طرف ہو.اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ غیر لکھی ہوئی چیز کے لئے کتاب کا لفظ لایا گیا ہے.کیونکہ بعض دفعہ جس بات کا ابتداء سے فیصلہ کر لیا گیا ہو اسی کے مطابق نام رکھ دیاجاتا ہے.جیسے ماں باپ اپنے بچوں کا نام عبدالرحمٰن رکھ دیتے ہیں جس کے معنے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو ظاہر کرنے والا.اب کیا اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ بچہ ماں کے پیٹ ہی میں یہ صفت ظاہر کرنے والا تھا ؟بلکہ اِس کے صرف اتنے معنے ہوتے ہیں.کہ وہ آئندہ بڑے ہو کر اس صفت کو ظاہر کرے گا.اِسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے.فَاَنْجَيْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ (الشعرآء : ۱۲۰)کہ ہم نے نوح ؑ اور اُس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا.اب اس کے یہ معنے نہیں کہ جو پہلے ہی بھری ہوئی تھی اُس میں انہیں سوار کیا کیونکہ جو کشتی پہلے سے بھری ہوئی ہو اُس میں سوار کرنے کے کیا معنے.بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کشتی میں سوار کیا جو اُن کے بیٹھنے کی وجہ سے بھر گئی.پس جو فعل آئندہ کسی سے صادر ہونے والا ہو اس کی وجہ سے بھی نام دے دیا جاتا ہے.اِسی طرح ذٰلِکَ الْکِتٰبُ کا الٓمّٓ کی طرف اشارہ نہیں کہ اس سے یہ سمجھا جائے کہ کتاب کا لفظ غیر لکھی ہوئی چیز کے لئے آیا ہے بلکہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک کامل کتاب بننے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اِس کے متعلق فیصلہ فرما چکا ہے.کتاب کا لفظ اس چیز کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے اندر کوئی لکھی ہوئی چیز ہو.جیسے قرآن کریم میں آتا ہے.وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ (الانعام: ۸۱) یعنی اگر ہم تجھ پر ایک کتاب نازل کرتے جو کاغذ وں پر ہوتی.غرض کتاب کے کئی معنے ہیں.محاورہ میں اس کے معنے ایسی چیز کے ہیںـ جسے قائم کر دیتے ہیں.یا جس کا اندازہ کر لیتے ہیںیا جسے واجب کر دیتے ہیںیا فرض کر دیتے ہیں یا پختہ کر لیتے ہیں.اِن سب کیلئے کتاب کا لفظ استعمال
Page 478
ہوتا ہے.پھر کَتَبَ کا لفظ قَضٰی کے معنوں میں بھی آتا ہے.جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا (التّوبة:۵۱) یعنی جس امر کا خدا نے فیصلہ کردیا ہے اور جسے ہمارے لئے مقدر کر دیا ہے وہی ہمیں پہنچے گا.(مفردات) اَلْحِکْمَۃُ : اس کے کئی معنے ہیں(۱) اَلْعَدْلُ انصاف(۲) اَلْعِلْمُ.علم(۳) اَلْحِلْمُ.دانائی(۴) مَا یَمْنَعُ مِنَ الْجَھْلِ جو بات جہالت سے روکتی ہو.(۵) وَضْعُ الشَّیْ ءِ فِیْ مَوْ ضِعِہٖ کسی چیز کو اُس کے مقام پر رکھنا(۶) اس کے ایک معنے صَوَابُ الْاَمْرِ وَ سِدَادُہٗ کے بھی ہیں یعنی صحیح اور درست کام.(اقرب) یُزَ کِّیْ : زَکّٰی کے معنے ہیں(۱) اس کو بڑھایا اور اسکی نشوونما کی.آگے نمو کے دو۲ معنے ہیں.اُسے اپنی ذات میں بڑھایا یا اُسے باسامان کیا(۲) اس کے ایک معنے تَطْھِیْرٌ کے بھی ہوتے ہیں.یعنی پاک کرنا اس لحاظ سے آیت کے یہ معنے ہیں کہ وہ لوگوں کو اُن کی ذات میں بڑھائے گا وہ ان کو با سامان کرے گا.وہ ان کو پاک کرے گا.پھر تَطْھِیْربھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ظاہری طہارت اور دوسرے باطنی طہارت.(اقرب) تفسیر.پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ان لوگوں میں سے جو اس جگہ رہیں گے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما.مِنْھُمْ اور اے ہمارے رب رسول کے آنے سے یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی کہ خانہ کعبہ سے جس طرح تعلق رکھنا ہے اُس کا پتہ لگ جائے گا.اور وہ سچے اور مخلص مومن بن جائیں گے مگر اے ہمارے ربّ ہم نے جو اپنی اولاد کو یہاں آکر بسایا ہے تو اس میں علاوہ اس غرض کے کہ تیرا نام بلند ہو ہماری یہ بھی غرض ہے کہ ہماری اولاد کے ذریعے تیرا نام بلند ہو.ہم نے صرف تیرا گھر نہیں بنایا بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہاں لا کر بسا دیا ہے.گویا ہم نے جو تیرے نام کی بلندی کی کوشش کی ہے اس میں کچھ اپنی غرض بھی شامل ہے.ہم نے یہ مکان بنایا ہے اس لئے کہ تیرا نام بلند ہو.اور ہم نے اپنی اولاد یہاں اس لئے بسائی ہے کہ اس کے ذریعہ سے تیرا نام بلند ہو.پس ہم نے جو اپنی اولاد یہاں بسائی ہے اس میں ہماری یہ غرض بھی شامل ہے کہ آنے والا رسول انہیں میں سے ہو باہر سے نہ ہو.یَتْلُوْاعَلَیْھِمْ اٰیٰتِکَ اور وہ تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سُنائے.تیرے نشانات اور معجزات کے ذریعے اُن کے ایمانوں کو تازہ کرے.اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے دلائل لوگوں کے سامنے بیان کرے.وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ اور تیری شریعت جس کے بغیر باطن پاکیزہ نہیں ہو سکتا اور جو انسان کو مکمل نمونہ بنا دیتی ہے نازل ہو اور وہ لوگوں کو سکھائے.
Page 479
وَ الْحِكْمَةَ اور اے ہمارے ربّ! جب وہ رسول آئیگا انسانی عقل تیز ہو چکی ہو گی.اس وقت انسان بچہ نہیں ہو گا کہ اُسے یہ کہا جائے کہ اُٹھ اور فلاں کام کر اور جب وہ کہے کہ میں کیوں کروں تو اُسے کہا جائے کہ آگے سے بکواس مت کرو.عیسیٰ ؑ کے زمانہ میں اور موسیٰ ؑ کے زمانہ میں ایسا ہو چکا ہے.مگر جب وہ نبی آئے گا اس کا زمانہ انسانی عقل کے ارتقاء کا زمانہ ہو گا.اس وقت بندہ یہ نہیں سُنے گا کہ کر.بلکہ پوچھے گا کہ کیوں کروں.پس اے خدا تو اس کو موسیٰ ؑ کی طرح صرف شریعت ہی نہ دیجیئو.نوح ؑ کی طرح صحف ہی نہ دیجیئو دائود ؑ کی طرح احکام ہی نہ دیجیئو بلکہ ساتھ ہی اُن کی وجہ بھی بتا دیجئیو اور ان احکام کی حکمت بھی واضح کیجیئو.تاکہ نہ صرف اُن کے جسم تیرے حکم کے تابع ہوں بلکہ ان کا دماغ اور دل بھی تیرے حکم کا تابع ہو اور وہ سمجھیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے فلسفہ کے ماتحت کہا گیا ہے.عقل کے ماتحت کہا گیا ہے.ضرورت کے ماتحت کہا گیا ہے.فوائد کے ماتحت کہا گیا ہے.وَ يُزَكِّيْهِمْ اور ان کو پاک کرے.دماغ کو ہی پاک نہ کرے بلکہ حکمت سکھا کر اُن کے قلوب کو بھی محبت الٰہی سے بھردے.یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ میں جذب کر دیں الہٰی صفات اُن میں پیدا ہو جائیں اور وہ چلتے ہوئے انسان نظر نہ آئیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ایک آئینہ دکھائی دیں اور وہ ایسے ذرائع اختیار کرے جن سے قوم کی ترقی کے سامان پیدا ہوں.اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.اے ہمارے رب! ہم نے جو چیز مانگی ہے بظاہر یہ نا ممکن نظر آتی ہے اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ تجھ میں طاقت ہے تو عزیز خدا ہے تو غالب خدا ہے اور تیری شان یہ ہے کہ ؎ جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے.چونکہ تو عزیز خدا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا رسول آئے.اس پر اعتراض ہو سکتا تھا کہ اگر پہلے خدا نے ایسا رسول نہیں بھیجا تو اب کیوں بھیجے اور اگر پہلے بھی ایسا رسول بھیجنا ضروری تھا تو پھر ایسے رسول کو نہ بھجوا کر بنی نوع انسان پر کیوں ظلم کیا گیا.اس اعتراض کا الحکیم کہہ کر ازالہ کر دیا کہ ہم جانتے ہیں پہلے ایسا رسول آہی نہیں سکتا تھا پہلے لوگ اس قابل ہی نہیں تھے کہ محمدؐی تعلیم کو برداشت کر سکیں.پس ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزیز کہہ کر خدائی غیرت کو جوش دلایا اور کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ غیر معقول نہیں.ہم جانتے ہیں کہ تو ایسا کر سکتا ہے مگر ساتھ ہی حکیم کہہ کر بتا دیا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اگر تو نے پہلے ایسا رسول نہیں بھجوایا تو نعوذ باللہ تو نے بخل سے کام لیا بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تو نے پہلے ایسا نبی نہیں
Page 480
بھیجا تو صرف اس لئے کہ پہلے ایسا نبی بھیجنا مناسب نہیں تھا.اس دعا میں ہمیں ایک عجیب بات نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف رُسُوْلًا فرمایا ہے رُسُلًا نہیں فرمایا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی اپنی اولاد کے متعلق ایسی واضح تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ان میں بہت سے رسول پیدا ہوںگے لیکن باوجود اس کے وہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک رسول کے مبعوث کئے جانے کی دُعا فرماتے ہیں.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات کھل چکی تھی کہ خاتم النبیّین بنی اسمٰعیل میں سے آنا ہے اور وہی ایک رسول ہے جس کی کتاب پر تمام شرائع کا اختتام ہے.میں نے دیکھا ہے کہ میرے اس قسم کے الفاظ پر غیر مبائعین کہا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول تو ایک ہی ہے مگر ہمیں اس سے کبھی انکار نہیںہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ہی ایک ایسے رسول ہیں جن کا سلسلہ نبوت قیامت تک منقطع نہیں ہو گا.اور ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو بھی آپ کی نبوت کے تابع اور اس کا ظل سمجھتے ہیں اور ظل اصل سے کوئی علیحدہ چیز نہیں ہوتی.پس اب کوئی نیا حکم نہیں کوئی نئی تعلیم نہیں کوئی نیا ارشاد نہیں کوئی نئی ہدایت نہیں.وہی ارشاد.وہی ہدایت.وہی تعلیم اور وہی احکام ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم دنیا میں لائے تھے اور جو قرآن کریم میں بیان ہیں اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مستقل نبی مانتے تو پھر تو اس بات کی ضرورت تھی کہ ہر چیز نئی ہوتی.مگر یہاں تو سب کچھ وہی ہے جو محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.صرف اتنی بات ہے کہ چونکہ لوگوں نے آپ ؐ کی تعلیم کو بھلا دیا تھا اور اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بروزِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا پس یہ رسالت کوئی الگ نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی ہی رسالت ہے اور اگر ضرورت کے ماتحت ایسے کئی نبی بھی آجائیں تو کوئی ہرج نہیں کیونکہ ان کے ذریعہ کوئی نیا دین جاری نہیں ہو گا.بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی زندہ ہو گا.بہر حال رُسُوْلًا کا لفظ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الہام سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث ہونے والا ہے.اَب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک نبی اُن میں مبعوث ہونے والا ہے تو انہوں نے اس کے لئے دعا کیوں کی.سو جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں الہام کا پورا کرنا خود اپنی ذات میں ایک نیکی ہوتا ہے اور الہام کے پورا کرنے کے لئے سب سے پہلا کام جو انسان کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ دُعا سے کام لے اور پھر اپنے عمل اور کوشش سے اُسے پورا کرے.نادان خیال کرتا ہے کہ الہٰی وعدہ کے بعد کوشش چھوڑ دینی چاہیے.حالانکہ
Page 481
یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے محبوب کی بات پوری کرنے کے لئے اپنا سارا زور صرف کر دیتا ہے.انبیاء کو چونکہ خدا تعالیٰ سے گہرا تعلق ہوتا ہے اس لئے اس کی بات کو پورا کرنے کے لئے وہ ہرقسم کی جدو جہد سے کام لیتے ہیں تاکہ اس کا نشان ظاہر ہو.پس اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے دعا کی تو یہ کوئی قابلِ اعتراض امر نہیں بلکہ اس امر کا ثبوت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی اور کامل عشق تھا قطع نظر اس بات کے کہ خدا تعالیٰ قادرِ مطلق ہے اور و ہ اسے خود پورا کر سکتا ہے انہوں نے خدا تعالیٰ سے اپنی کامل محبت کا ثبوت دیدیا.اور اُسی وقت دعا کی.کہ اے ہمارے رب! ان میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما.تنوین تحقیر کے لئے بھی آتی ہے اور تعظیم کے لئے بھی.یہاں تعظیم کے لئے آئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما.میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بتاتی ہے کہ گو وہ جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں بہت سے رسول آنے والے ہیں.مگر وہ چاہتے تھے کہ آخری رسول جو دُنیا کا نجات دہندہ بن کر آنے والا ہے وہ بنو اسحاق سے نہ ہو بلکہ بنو اسمٰعیل میں سے ہو.کیونکہ اس وقت تک بنواسحاق کو کافی حصّہ مل چکا ہو گا مسیحی مصنّفین دعائے ابراہیمی کے اس حصہ پر بالعموم یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ بائیبل میں اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولاد کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی وعدہ کیا گیا تھا دوسرے اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولادکی نسبت کوئی وعدہ تھا تو اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمٰعیل ؑ کی اولاد میں سے تھے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ بائیبل کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمٰعیل ؑ اور آپ کی نسل سے بنو اسحٰق کو شدید نفرت تھی اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی دادی حضرت سارہؓ کو ہاجرہؓ اور اسمٰعیل سے نفرت تھی جس کا اثر آئندہ نسل میں بھی منتقل ہونا بعید از قیاس امر نہیں.اسی وجہ سے حضرت ابراہیم ؑ ہاجرہؓ اور اسمٰعیل ؑ کو ایک دُور دراز مقام پر چھوڑ آنے پر مجبور ہوئے.بائیبل کہتی ہے کہ : ’’سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابرہام سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے تب اس نے ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے.کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اضحاق کے ساتھ وارث نہ ہو گا.‘‘ (پیدائش باب۲۱ آیت۹،۱۰) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو یہ بات ناگوار گذری مگر آخر خدا تعالیٰ نے انہیںکہا کہ: ’’تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث بُرا نہ لگے جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی
Page 482
بات مان.‘‘ (پیدائش باب ۲۱ آیت۱۲) بنو اسمٰعیل اور بنو اسحاق کی اس باہمی رقابت کی طرف بائیبل کی اس پیشگوئی میں بھی اشارہ موجود ہے جو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے متعلق کی گئی تھی کہ:.’’اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اُس کے خلاف ہوں گے.‘‘ (پیدائش باب۱۶ آیت۱۲) پس اس باہمی رقابت اور پھر اس انسانی دست بُرد کی وجہ سے جس کا بائیبل تختہ مشق بنی رہی اگر اُس میں حضرت اسمٰعیل ؑ اور ان کی اولاد کی نسبت کوئی واضح پیشگوئی موجود نہ ہوتو محض اس بنا پر قرآنی شہادت کو رد ّکر دینا قرینِ انصاف نہیں کہلا سکتا جس طرح بائیبل کی شہادت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنو اسحاق سے کوئی وعدہ تھا اسی طرح قرآن کریم کی شہادت سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ بنو اسمٰعیل سے بھی کوئی وعدہ تھا.لیکن اگر اس نظریہ کو درست تسلیم نہ کیا جائے تب بھی بائیبل ایسے اشارات سے خالی نہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمٰعیل ؑ کی نسل بھی خاص انعامات کی وارث ہو گی.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو الفاظ حضرت اسحاق ؑ کی اولاد کے متعلق بائیبل میں استعمال ہوئے ہیں وہی حضرت اسمٰعیل ؑ کے متعلق بھی استعمال ہوئے ہیں.اور جس طرح حضرت اسحٰق ؑ کی اولاد کو بڑھانے اور ان میں سے بادشاہ پیدا کرنے کا وعدہ پیدائش باب ۱۷ آیت ۱۶ میں ہے اسی طرح حضرت اسمٰعیل ؑ کی اولاد کو بڑھانے اور ان میں سے سردار پیدا کرنے کا وعدہ پیدائش باب۱۷آیت۲۰ میں ہے پس جس قسم کے انعامات کا وارث حضرت اسحاق ؑ کی اولاد کو قرار دیا گیا ہے اُسی قسم کے انعامات کا وارث بنو اسمٰعیل کو بھی تسلیم کرنا پڑےگا اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت اسحاق ؑکی نسبت اس باب کی آیت۲۱ میں لکھا ہے کہ: ’’میں اپنا عہد اضحاق سے باندھوںگا.‘‘ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اس نسل سے ہوں گے تو یہ دلیل بھی معقول نہیں کیونکہ اسحاق ؑکی پیدائش سے بھی پہلے خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد کیا تھا اور اس میں یہ شرط لگائی تھی کہ اس عہد کی علامت ختنہ ہو گی(پیدائش باب۱۷ آیت ۱۱) اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کا بھی ختنہ کیا.(پیدائش باب۱۷ آیت۲۵) اگر وہ عہد صرف اسحاق ؑ اور اس کی نسل سے ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اپنا ختنہ کراتے.کیونکہ اُن سے عہد تھا.اپنے غلاموں کا کرواتے کیونکہ ان کی نسبت حکم تھاحضرت اسحاق ؑ کا کرواتے کیونکہ ان سے اس عہد نے پورا ہونا تھا.تیرہ سالہ لڑکے اسمٰعیل کا ختنہ کس سبب سے کروایا گیا.اس کی
Page 483
صرف ایک ہی وجہ تھی کہ اس کی نسل سے بھی اس عہد نے پورا ہونا تھا پس آپ کا حضرت اسمٰعیل ؑ کا بھی ختنہ کرانا ایک صاف ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت اسمٰعیل ؑ بھی آپ کی اولاد میں سے تھے جس کے ساتھ وہ عہد پورا ہونا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو اسمٰعیل میں ختنہ کا رواج ہمیشہ رہا اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حکم نہ صرف اسمٰعیل کے لئے بلکہ اس کی اولاد کے لئے بھی سمجھا گیا تھا.پس عہد جس طرح حضرت اسحاق ؑکی اولاد کے لئے تھا.اسی طرح حضرت اسمٰعیل ؑ کی اولاد کے لئے بھی تھا.باقی رہا پیدائش باب ۱۷ آیت۲۱ کا مطلب کہ ’’میں اپنا عہد اضحاق سے باندھوںگا‘‘ سو دوسرے حالات کو مدِّنظر رکھ کر آیت کا یہ مطلب ہے کہ اس ابدی عہد کی ابتداء بنو اسحاق سے شروع ہو گی.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عہد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق تھا ابتداء میں بنو اسحاق سے ہی پورا ہوا.لیکن بائیبل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عہد بنو اسمٰعیل کے بارہ میں بھی تھا.کیونکہ ختنہ کا حکم انہیں بھی دیا گیا تھا جیسا کہ لکھا ہے:.’’جب اس کے بیٹے اسمٰعیل کا ختنہ ہوا تووہ تیرہ برس کا تھا.‘‘ ( پیدائش باب ۱۷ آیت۲۵) اور اسمٰعیل کے متعلق بھی برکت کا وعدہ کیا گیا تھا جیسا کہ لکھا ہے: ’’اور اسمٰعیل کے حق میں بھی میں نے تیر ی دعا سُنی.دیکھ میں اُسے برکت دوں گا اور اُسے برومند کروںگا اور اُسے بہت بڑھائو ںگا.‘‘ (پیدائش باب۱۷ آیت۲۰) اسی طرح پیدائش باب۲۱ آیت ۱۸میں لکھا ہے:.’’میں اس (اسمٰعیل) کو ایک بڑی قوم بنائوں گا.‘‘ پس ضروری تھا کہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام بھی اس برکت میں شامل ہوتے گو وہ اس عہد میں شامل نہ تھے جو کنعان کے قبضہ کے متعلق تھا.کیونکہ وہ وعدہ صرف اسحاق ؑ کی نسل کے ساتھ پورا ہونا تھا.لیکن یہود و نصاریٰ غلطی سے یہ سمجھنے لگ گئے کہ برکت کا عہد صرف اسحاق ؑ کی اولاد سے تھا.حالانکہ ابراہیمی عہد کی دو۲ شکلیں تھیں ایک مجمل اور ایک مفصّل.مجمل عہد تو یہ تھا کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا اور نسل سے مراد اسحٰق اور اسمٰعیل دونوں تھے.اور مفصّل عہد آگے دو۲ حصوں میں منقسم تھا.اسحاق ؑ کی نسبت تو یہ عہد تھا کہ کنعان کی حکومت اسے نسلاً بعد نسلٍ حاصل ہوگی اور اسمٰعیل کی نسبت بائیبل صرف اتنا بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے برکت دوں گا اور برومند کروں گا.یہ برکت اُسے کس طرح دی گئی؟ اس کا جواب ہمیں بائیبل سے نہیں بلکہ قرآن کریم سے ملتا ہے قرآن کریم بتاتا
Page 484
ہے کہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے متعلق یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے اور اس کی اولاد کو مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح پر حکومت دی جائے گی اور خدا تعالیٰ ان کے مرکز کو ہمیشہ دشمن کے حملہ سے محفوظ رکھے گا اور تمام علاقہ پر ان کی روحانی اور جسمانی حکومت ہو گی.اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے گا.جو تمام دنیا کی ہدایت کا موجب ہو گا.پس یہ غلط ہے کہ بنو اسمٰعیل کے ساتھ برکت کا کوئی وعدہ نہ تھا بائیبل کی خود اندرونی شہادات بتا رہی ہیں کہ نسلِ اسمٰعیل کی ترقی کا بھی وعدہ کیا گیا تھا.اور ضروری تھا کہ جس طرح بنو اسحاق کو ترقی دی گئی اسی طرح بنو اسمٰعیل کو بھی ترقی دی جاتی.اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا.باقی رہا یہ سوال کہ اگر حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی وعدہ ثابت بھی ہو تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے.تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ کسی خاص قوم کے کسی بزرگ انسان کی اولاد سے ہونے کا حقیقتاً ایک ہی ثبوت ہوتا ہے اور وہ اس قوم کی روایات ہیں جو نسلاًبعدنسلٍ چلتی چلی جاتی ہیں تمام قوموں اور خاندانوں کے کسی خاص شخص سے متعلق ہونے کا اس کے سوا اور کیا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ قوم ایسا بیان کرتی ہے پھر اس معاملہ میں کیوں عربوں کے بیان کو تسلیم نہ کیا جائے جبکہ قریش کا دعویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے کا تھا کہ وہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور تمام عرب اس بات کو تسلیم کرتے تھے خود کعبہ میں حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کا بُت بنا کر رکھا ہوا تھا پھر قریش کے بنی اسمٰعیل ہونے میں کیا شک ہو سکتاہے.حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کوئی ایسی دنیوی شہرت نہ رکھتے تھے کہ خیال کیا جائے کہ عرب کی بعض اقوام نے اس عزت میں حصّہ لینے کے لئے اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر دیا ہو.پس ایک قوم کا دعویٰ جو صدیوں سے چلا آتا ہے کسی طرح ردّ نہیں کیا جا سکتا جبکہ جھوٹ کا کوئی محرک بھی دکھائی نہیں دیتا.دوسرا ثبوت قریش کے بنو اسمٰعیل ہونے کا یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹے طور پر بنو اسمٰعیل بن گئے تھے تو اصل بنواسمٰعیل ان کے اس قول کو ردّ کرتے لیکن کسی قوم کا ان کے دعویٰ کو ردّ کرنا ثابت نہیں.سوم پیدائش باب۱۷ آیت۲۰ میں لکھا ہے کہ ’’میں اسماعیل کو ایک بڑی قوم بنائوں گا.‘‘ اگر قریش آپ کی اولاد نہیں تو وہ بڑی قوم کون سی ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا.کیونکہ پیشگوئی چاہتی ہے کہ وہ قوم شناخت بھی ہو.ورنہ اس کے پورا ہونے کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے.پس چونکہ قریش ہی اس بات کے مدعی ہیں اس لئے ان کا دعویٰ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا.
Page 486
ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہو گا.کچھ آیات اُتریں گی اور وہ سنادے گا پھر اور اُتریں گی اور وہ سنا دے گا.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کلام کے نزول کی کیفیت بھی بتا دی گئی تھی اور سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ اکٹھا نہیں اُترے گا.بلکہ آہستہ آہستہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اُترے گا قرآن کریم کے آہستہ آہستہ نازل ہونے میں حکمت یہ تھی کہ اگر اکٹھی تمام شریعت نازل ہو جاتی تو انسان گھبرا جاتا اور کہتا کہ میں اس پر کس طرح عمل کروں.مگر جب ایک ایک ٹکڑا نازل ہوا تو لوگوں کے لئے عمل کرنا آسان ہو گیا اور بتدریج وہ ترقی کرتے چلے گئے.غرض یَتْلُوْاعَلَیْھِمْ اٰیٰتِکَ میں قرآن کریم کے نزول کی کیفیت بتائی گئی ہے اور اس میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ کلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نازل ہو گا.آیت کے ایک معنے علامت کے بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ کے معنے یہ ہوںگے کہ وہ تیری علامات لوگوں کو بتائے.اس میں یہ اشارہ مخفی تھا کہ وہ ایسا کلام پیش کرے گا جس سے خدا تعالیٰ کا وجود نظر آجائے گا.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.لَاتُدْرِکُہُ الْاَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارَ(الانعام:۱۰۴)یعنی آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتیں مگر وہ اپنے کلام کے ذریعہ بینائیوں تک پہنچ جاتا ہے.پس اس کے دوسرے معنے یہ ہیں کہ وہ ایسی علامتیں لوگوں کو بتائےگا جن سے خدا تعالیٰ کا وجود پہچانا جائےگا.اور ایسے دلائل پیش کریگا جن سے انہیں خدا تعالیٰ نظر آجائےگا.یہ دلائل آگے دو قسم کے ہوتے ہیں.ایک عقلی اور دوسرے اعجازی.پس یَتْلُوْا عَلَیْھِمْ اٰیٰتِکَ میں بتایا کہ وہ ان عقلی امور کی طرف بھی لوگوں کی راہنمائی کریگا جو خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے ہیں اور ان معجزات اور نشانات کو بھی پیش کرےگا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں.آیت کے ایک معنے چونکہ عذاب کے بھی ہوتے ہیں اس لئے یَتْلُوْا عَلَیْھِمْ اٰیٰتِکَ سے یہ استنباط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف عذاب کی خبریں دےگا.پھر آیت کے ایک معنے چونکہ اونچی عمارت کے بھی ہیں اس لئے یَتْلُوْا عَلَیْھِمْ اٰیٰتِکَ کایہ مطلب بھی ہے کہ اس کی تعلیم میں تدریجی ارتقاء ہو گا.جیسے عمارت پر عمارت بنتی ہے اور وہ اپنے اندر مومنوں کے لئے بھاری ترقیات کے سامان رکھتی ہو گی.يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ اس کے ایک معنے تو یہ ہیں کہ وہ انہیں ایسی تعلیم دے گا جو ساری کی ساری لکھی ہوئی ہو گی.کیونکہ عربی زبان میں ہر اس چیز کو کتاب کہا جاتا ہے جس میں مختلف مسائل کا ابواب وار اندراج ہو.اس لحاظ سے صرف قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے.جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی وفات پر صحابہؓ کو لکھی ہوئی ملی.
Page 487
اور صرف مسلمان ہی دنیا میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن شروع سے اب تک محفوظ صورت میں لکھا ہوا چلا آرہا ہے.یہ خصوصیت کسی اور الہامی کتاب کو ہرگز حاصل نہیں.کیونکہ دوسری کوئی کتاب بھی لکھی ہوئی نہ تھی.کوئی سینکڑوں سال بعد جمع کی گئی اور کوئی کتاب اگر اس وقت لکھی بھی گئی تو اسے یہ خصوصیت حاصل نہ تھی کہ اس کا لفظ لفظ الہامی ہو.بائیبل کے متعلق یہ کبھی بحث نہیں ہوئی کہ یہاں زبر ہے یا زیر ہے.لیکن قرآن کریم کے متعلق یہ بحث ہوتی تھی کہ یہاں زبر ہے یا زیر ہے بلکہ یہاں تک بھی بحث ہوتی تھی کہ یہاں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا.غرض اس میں بتایا کہ وہ رسول ایک ایسی کتاب کی تعلیم دیگا جو بالکل محفوظ ہو گی اور اس کے زمانہ میں ہی لکھی جا چکی ہو گی.پھر کتاب جمع کرنے والی چیز کو بھی کہتے ہیں.اس لحاظ سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی تعلیم دے گا جو تمام قسم کے علوم اور تعلیموں پر حاوی ہو گی اور ہر قسم کی اخلاقی‘ تمدنی،مذہبی اور اقتصادی تعلیم کی جامع ہو گی.کتاب کے ایک معنے چونکہ فرض کے بھی ہیں اس لحاظ سے یُعَلِّمُھُمُ الْکِتَابَ کے یہ معنے بھی ہیں کہ وہ ایسی تعلیم دے گا جس پر عمل کرنا لوگوں کے لئے فرض ہو گا.گویا وہ تمام ضروری باتیں جن کے بغیر روحانی زندگی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی اس کے ذریعہ لوگوں کو بتادی جائیںگی.پھر کتاب کے ایک معنے حکم کے بھی ہیں.اگر حکم کو فرض کا ہم معنے سمجھ لیا جائے تب تو اس کے کوئی علیٰحدہ معنے نہیں ہوں گے.لیکن اگر حکم کو فرض سے الگ سمجھا جائے تو پھر یہ مراد ہو گی کہ بعض احکام تو فرض ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں.جو فرائض قطعی ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں قائم رہتے ہیں جیسے نماز ہے.لیکن بعض حکم ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے مطابق بدل جاتے ہیں.مثلاً اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم سزا میں فائدہ دیکھو تو سزا دو اور اگر معاف کرنے میں فائدہ دیکھو تو معاف کر دو.پس جو احکام بدلتے نہیں وہ فرائض ہیں اور جو ضرورت کے ماتحت تبدیل ہو جاتے ہیں وہ حکم ہیں.ایسے احکام کو حکم اس لئے قرار دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ حکمت سے نکلا ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم خود سوچ لو کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے.فرض کی صورت میں تو اس نے کسی اور پر بات نہیں چھوڑی لیکن احکام میں اس نے رعایت دیدی ہے مثلاً فرض نمازوں کی اس نے خود ہی رکعات مقرر کر دی ہیں جن کو انسان گھٹا بڑھا نہیں سکتا لیکن نوافل اس نے انسان کی مرضی پر رکھ دیئے کہ جتنی توفیق ہو پڑھ لو.اس فرض کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیرِ تفسیر آیت کے یہ معنے ہوںگے کہ وہ ایسی کتاب ہو گی جو تمام احکام کی جامع ہو گی.خواہ وہ لازمی ہوں یا اختیاری.پھر کتاب کے ایک معنے قضاء آسمانی کے بھی ہیں.اس لحاظ سے وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ کے یہ معنے ہوںگے کہ وہ
Page 488
ان کو تقدیر الہٰی کا علم دیگا.درحقیقت اگر غور سے کام لیا جائے تو تقدیر کا صحیح علم دینے والا صرف قرآن کریم ہی ہے.باقی سب لوگ یا تو جبرؔ کی طرف چلے گئے ہیں یا قدر کی طرف مائل ہو گئے ہیں.جس کتاب نے جبروقدر کا صحیح مفہوم بیان کیا ہے وہ صرف قرآن کریم ہی ہے.افسوس ہے کہ قرآن کریم کے ماننے والوں میں سے بھی بعض قدرؔی اور بعض جبریؔ بن گئے ہیں.حالانکہ صحیح مذہب ان کے بین بین ہے.میں نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سنا ہے.آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جتنا غور کیا ہے ہمیں یہی معلوم ہوا ہے کہ صرف قدر کے عقیدہ سے بھی امن اُٹھ جاتاہے اور صرف جبر کے عقیدہ سے بھی امن اُٹھ جاتا ہے.اگر یہ سمجھا جائے کہ صرف قدر ہی قدر ہے اور انسان تارک الدنیا ہو جائے تو وہ نیکیوں میں ترقی نہیں کر سکتا اور اگر جبر کا عقیدہ اختیار کر لیا جائے تو وہ سمجھے گا کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس سے کرواتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اسے کسی بدی سے بھی عار نہیں رہے گی کیونکہ وہ اسے خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر دےگا.غرض صحیح عقیدہ ان دونوں کے درمیان ہے اور انسانی اعمال کی مثال ایک ایسے گھوڑے کی سی ہے جو لمبی رسی سے بندھا ہو ا ہو.وہ یہ خیال کر کے کہ میں آزاد ہوں چلتا پھرتاہے مگر آخر اسے جھٹکا لگتا ہے اور رُک جاتا ہے.اسی طرح انسان مقیّد بھی ہے اور مختار بھی.انسان مختار ہے ایک حد کے اندر اور مقیّد ہے ایک حد کے اندر جو قید کونہیں سمجھتا وہ بھی گمراہ ہے اور جو اختیار کو نہیں سمجھتا وہ بھی گمراہ ہے اور یہ علم صرف قرآن کریم سے ہی حاصل ہوتا ہے.وَ الْحِكْمَةَ:حکمت کے ایک معنے چونکہ عدل کے بھی ہیں.اس لئے حکمت سکھانے کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ وہ عدل سکھائیگا.اس کی تعلیم میں ظلم بالکل نہ ہو گا.اس کے یہ معنے بھی ہیں کہ وہ علم کو کامل کریگا.یعنی بعض شریعتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف حکم دیتی ہیں علم نہیں دیتیں.وہ کہتی تو ہیں کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو.مگر اس کی وجہ نہیں بتاتیں.ان میں صرف امر کا حصہ ہوتا ہے لیکن علم کا حصہ نہیں ہوتا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلی شریعتوں میں جو احکام دیئے گئے ان کی بھی حکمتیں تھیں مگر وہ حکمتیں بتائی نہیں جاتی تھیں.مگر قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسی تعلیم ہو گی جس کے ساتھ احکام کی حکمت اور وجہ بھی بتائی جائیگی.وہ بتائےگا کہ نماز پڑھو.کیونکہ اس میں یہ حکمت ہے.یا چوری نہ کرو کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے.وہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ نہ بولو اور ظلم نہ کرو بلکہ وہ جھوٹ نہ بولنے اور ظلم نہ کرنے کی وجہ اور حکمت بھی ساتھ بتائے گا.اور عمل کے ساتھ علم کا حصہ بھی شامل کرے گا.حکمت کے ایک معنے حلم یعنی دانائی کے بھی ہیں.یعنی موقعہ اور محل کی شناخت.یہ چیز علم سے کسی قدر اختلاف
Page 489
رکھتی ہے.علم تو کہتاہے کہ ایسا کرو یا نہ کرو لیکن دانائی بتاتی ہے کہ فلاں موقعہ پر یوں کرو اور فلاں موقعہ پر یوں.پس اس کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ وہ مقررہ احکام کی تو حکمت بتا ئےگا اور جو معیّن احکام نہیں بلکہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان میں دانائی کی راہ سکھلائےگا اور بتائےگا کہ فلاں جگہ اس طرح کرو اور فلاں جگہ اس طرح.حکمت کے ایک معنے نبوت کے بھی ہیں.اس لحاظ سے اس کے معنے یہ ہیں کہ اس رسول کے ذریعے انہیں نبوت کا مقام حاصل ہو سکے گا.اس کے ایک معنے وَضْعُ الشَّیْ ئِ فِی مَوْضِعِہٖ کے بھی ہیں مگر یہ معنے دانائی میں ہی آجاتے ہیں اسی طرح اس کے معنے مَا یَمْنَعُ مِنَ الْجَھَالَۃِ کے بھی ہیں.یعنی ایسی وجوہ جو کسی بُرے کام سے روکنے والی ہوں.مگر یہ معنے بھی پہلے معنوں میں آجاتے ہیں.پس اصل میں اس کے چار معنے ہیں(۱)عدل (۲) علم (۳) حلم (۴)نبوت.وَ يُزَكِّيْهِمْ میں ان معنوں کے لحاظ سے جو حل لغات میں بیان کئے جا چکے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ (۱) وہ ان کی تعداد کو بڑھا ئیگا.یعنی اس کے کلام میں غیر معمولی تاثیر ہو گی جس کی وجہ سے لوگ اُسے قبول کرتے چلے جائیں گے اور اس کا مذہب دنیا پر غالب آنیوالا مذہب ہو گا.اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا ہے کہ تَزَ وَّجُوْاالْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَاِنِّیْ مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْاُمَمَ.(ابو داؤد کتاب النکاح باب النھی عن تزویج من لم یلد من النّساء و نسائی کتاب النکاح) کہ بہت بچے جننے والی اور محبت کرنے والی عورتوں سے شادیاں کرو.کیونکہ میں باقی اُمتوں پر تمہاری کثرت کو پیش کر کے قیامت کے دن فخر کروں گا.غرض تعداد کا بڑھانا خواہ نسلی لحاظ سے ہو یا تبلیغی لحاظ سے يُزَكِّيْهِمْ میں ہی شامل ہے.پھر اسلامی تعلیم بنیادی طور پر ایسے امور پر مشتمل ہے جن سے مسلمان دنیوی لحاظ سے بھی غیر معمولی ترقی کر سکتے ہیں.مثلاً ایک بڑی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ خُذْ مِنْ اَمْوَالِھِمْ صَدَ قَۃً تُطَھِّرُ ھُمْ وَتُزَکِّیْھِمْ بِھَا (التّوبة :۱۰۳) یعنی اے محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) تو اپنی اُمت کے لوگوں سے مال لے اور اس کے ذریعہ اُن کو پاک کر اور اُن کو بڑھا یہ قا نون جو اسلام نے قائم فرمایا ہے دنیا کی اور کسی مذہبی کتاب میں نہیں.صرف اسلام ہی ہے جس نے ایک قومی فنڈ مقرر کیا ہے جس کی غرض یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے غرباء کی طاقت کو بڑھایا جائے.اور انہیں بھی ترقی کی دوڑ میں اُمراء کے دوش بدوش کھڑا کیا جائے.یہ مال جن مقامات پر خرچ کیا جاسکتا ہے ان میں سے ایک مُؤَلَّفَۃُ الْقُلُوْبِ ہیں.اس کا یہ مطلب نہیں کہ روپیہ دیکر دوسروں کو مسلمان بنایا جائے.بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرمذاہب میں سے جو لوگ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہوں انہیں لٹریچر مہیا کیا جائے اور انہیں حق کی تلاش میں مدد دی جائے.پھر اس
Page 490
کا ایک مصرف مساکین ہیں اور مساکین سے وہ لوگ مراد ہیں جو کمائی نہیں کر سکتے اور جو دوسروں پر بوجھ بنے ہوئے ہوتے ہیں.جب کسی قوم میں ایسے لوگ ہوں تو اُن کو دیکھ کر دوسروں کو بھی سوال کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اُن کی غیرت مٹ جاتی ہے.اگر ایک فنڈ ہو جس سے ان کی مدد کی جائے تو قوم میں سوال کرنے کی عادت پیدا نہیں ہوتی.اسلامی طریق یہی ہے کہ لوگوں کی ضروریات کو جہاں تک ہو سکے خود پورا کیا جائے اور جماعتی نظام ان کا خیال رکھے اور ان کے مانگنے کے بغیر ہی ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے اور جو لوگ بغیر ضرورت کے مانگیں ان کی سفارش نہ کی جائے اس کے بغیر قوم کا تزکیہ نہیں ہو سکتا.پھر مسکین خالی وہ شخص نہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو بلکہ مسکین وہ بھی ہے جو کوئی پیشہ تو جانتا ہو مگر اس کے پاس اتنا روپیہ نہ ہو کہ وہ ضروری آلات خرید سکے.ایسے شخص کے متعلق بھی ضروری ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور اُسے اپنے فن سے تعلق رکھنے والی ضروری اشیاء اور آلات مہیا کئے جائیں.اسی طرح جو بیوگان اور یتامیٰ ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے.یہ تمام باتیں یُزَکِّیْھِمْ میں شامل ہیں کیونکہ اس طرح قوم کے افراد ترقی کر سکتے ہیں.پھر تزکیہ سے ظاہری صفائی بھی مراد ہے جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ راستہ میں کوئی گند نہ پھینکا جائے کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے.سایہ دار جگہوں میں جہاں لوگ آرام کرتے ہیں پاخانہ نہ پھرا جائے.اسی طرح وضو کرنا، جمعہ کے دن نہانا، بدن اور لباس کی میل دُور کرنا ، ناک کان اور بالوں کی صفائی کرنا اور ناخنوں کے اندر میل جمنے نہ دینا.یہ تمام امور یُزَکِّیْھِمْ میں شامل ہیں.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص بُودار چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے.(ترمذی ابواب الطہارة.مسلم کتاب الطہارة باب خروج الخطایا.بخاری کتاب الجمعة و کتاب الاستیذان و کتاب الاطعمة) کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے.پھر قلبی صفائی ہے اس کے متعلق بھی اسلام اعلیٰ درجہ کی تعلیم کا حامل ہے.اخلاقی تعلیم ہے اس کے متعلق بھی اسلام نے بڑا زور دیا ہے اور کہا ہے کہ غیبت نہ کرو.چغلی نہ کرو.حسد نہ کرو.دوسروں پر ظلم نہ کرو.تجارتی بد دیانتی نہ کرو.حساب کتاب صاف رکھو.لین دین کے معاملات تحریر میں لے آیا کرو.سود نہ لو.قرض دو تو لکھ لیا کرو.قرض لو تو مقررہ وقت کے اندر ادا کرو.غرض تزکیہ نفوس کے لئے تمام ضروری احکام اور ان کی تفصیلات قرآن کریم نے بیان کر دی ہیں اور اس نے انسانی اعمال اور جذبات اور فکر کا ایسا تزکیہ کیا ہے جس کی مثال کسی اور مذہب میں نظر نہیں آسکتی اور جس سے دُعائے ابراہیمی کے پورا ہونے کا ایک زبردست ثبوت ملتا ہے.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے خدا! تو ان میں ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے.چنانچہ اللہ
Page 491
تعالیٰ نے آپ کی دُعا کو قبول فرماتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسلِ اسمٰعیل میں سے مبعوث فرما دیا اور وہ تمام کام آپؐ نے کر دکھائے جن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواہش کی تھی.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو دُعائے ابراہیمی کا مصداق قرار دیا ہے اور آپ نے فرمایا ہے.اَ نَا دَعْوَۃُ اَبِیْ اِبْرَاھِیْمَ(جامع البیان زیر آیت ھذا ) یعنی میں وہ شخص ہوں جو اپنے دادا ابراہیم ؑ کی دُعائوں کے مطابق دنیا کی اصلاح کے لئے کھڑا کیا گیا ہوں.پس یہ ایک بہت بڑی دُعا ہے جو اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے.اِنَّکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ.اس جگہ خدا تعالیٰ کی دو۲ صفات عزیز اور حکیم کا اس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ دُعائے ابراہیمی کا ایک حصہ صفت عزیز سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا صفت حکیم سے.یَتْلُوْا عَلَیْھِمْ اٰیٰتِکَ اور يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ والا حصہ صفت عزیز کے ماتحت ہے کیونکہ غالب خدا ہی بندوں تک پہنچ سکتا ہے.بندہ اپنی ذاتی جدوجہد سے اس تک نہیں پہنچ سکتا اور پھر غالب خدا کا ہی یہ حق ہے کہ احکام دے.دوسری طرف حکیم ہستی ہی دوسروں کو حکمت سکھا سکتی ہے اور تزکیہ بھی حکمت ہی کے ماتحت ہوتا ہے.اگر حکمت سمجھائے بغیرکوئی بات منوائی جائے تو دل اس کا تابع نہیں ہو سکتا دل تبھی مانے گا جب وہ اس کی حکمت معلوم کرلے گا.اسی طرح تزکیہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دل پر اثر نہ ہو.غرض اس دُعا کا ایک حصّہ صفت عزیز سے اور دوسرا صفت حکیم سے تعلق رکھتا ہے.یہی چار مقاصد خلافتِ اسلامی کے فرائض سے بھی تعلق رکھتے ہیں.یعنی دلائل سکھانا.خدا کی باتیں لوگوں کو بتانا.شریعت سکھانا.ایمان تازہ کرنے کے لئے قرآن کریم کے احکام اور ان کی حکمتیں بتانا.جسمانی و قلبی طہارت پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور یہی مبلّغوں، کارکنوں، پریذیڈنٹوں امیروں اور سکریٹریوں کا کام ہے.جب تک ان چاروں باتوں کو مدّنظر نہ رکھا جائے اُس وقت سلسلہ کی غرض و غایت پوری نہیں ہو سکتی.ابتدائے خلافت میں میں نے منصب خلافت میں ان باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیا تھا.تاکہ لوگ اس طرف توجہ کریں اور اُنہیں بار بار مجھ سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے کہ ہمیں بھی کوئی کام بتایا جائے.مگر بہت کم لوگ اس طرف توجہ کرتے ہیں.پس جو دوست سلسلہ کی خدمت کا شوق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ لیں اور خود ہی دیکھ لیں کہ ان کے کیا فرائض ہیں.ان کی سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ وہ ان چاروں کاموں کو پورا کریں.یہی وہ کام ہیں جن کے لئے اسلام نبوت خلافت اور امامت قائم کرتا ہے.پس نبی کا بھی اور پھر اس کے بعد خلفاء اور ان کے تابعین کا بھی یہی کام ہوتا ہے اور جو شخص ان کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے انصار میں شامل کر لیتا ہے.
Page 492
اس رکوع کی آیت۱۲۳، ۱۲۴ میں یہ بتانے کے لئے کہ جو مضمون شروع کیا گیا تھا وہ ختم کیا جاتا ہے پھر اُسی مضمون کے الفاظ لائے گئے ہیں جو آیت۴۱ میں تھے.اور فرمایا کہ دیکھو ہم نے اپنا عہد پورا کیا اور تمہیں لوگو ں پر فضیلت دی مگر اس کے مقابلہ میں تم نے جو شکر کیا وہ یہ ہے پس اب تم میں نبی نہیں آسکتا.تم ایمان لائو ورنہ عذاب الہٰی جب نازل ہوتا ہے تو نہ شفاعت کام دیتی ہے اور نہ تاوان.آیت۱۲۵ میں بتایا کہ نبوت سے بنی اسرائیل کو محروم کرنا بھی اسی عہد کے مطابق ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولادکے متعلق کیا گیا.آیت۱۲۶ ،۱۲۷ میں اس سوال کا جواب دیا جو بنی اسرائیل کو نبوت سے محروم رکھنے پر پیدا ہوا تھا کہ اب نبی کس قوم سے پیدا ہونا چاہیے.فرمایا کہ بنواسمٰعیل سے.چنانچہ اس کے لئے تعمیر کعبہ کا واقعہ یاد دلایا جس میں حضرت ابراہیم ؑ کے ساتھ حضرت اسمٰعیل ؑ بھی شامل تھے.اور دونوں نے بہت دعائیں کی تھیں جو رائیگاں نہیں جا سکتیں.آیت۱۲۸،۱۲۹،۱۳۰ میں ان دُعائوں کا ذکر کیا اور اس نبی کے کاموں کی تفصیل بتائی جس کے مبعوث ہونے کی دعا کی گئی تھی.اور ان دعائوں کو بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بنو اسحٰق کی ترقی کے علاوہ بنو اسمٰعیل کی ترقی کے لئے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی.پس جب بنو اسحٰق اپنی بداعمالیوں سے نبوت کے انعام سے محروم کئے گئے تو ان کے بعد بنو اسمٰعیل حق دار تھے کہ نبوت کا انعام انہیں ملتا.پس آنے والا بنی اسماعیل میں سے ہونا چاہیے تھااور انہیں میں سے آیا ہے.وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ١ؕ وَ لَقَدِ اور اس شخص کے سوا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہو ابراہیم کے دین سے کون اعراض کر سکتا ہے؟اور ہم نے اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا١ۚ وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ۰۰۱۳۰ یقیناً اسے (اس) دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں (شمار) ہو گا.حَلّ لُغَات.سَفِہَ.(۱) سَفِہَ نَصِیْبَہٗ کے معنے ہیں نَسِیَہٗ اپنا حصہ بھول گیا.(۲)سَفِہَ نَفْسَہٗ کے معنے ہیں حَمَلَہٗ عَلَی السَّفَہِ.اُسے بیوقوفی پر آمادہ کیا(۳) اَھْلَکَہٗ اپنی جان کو ہلاک کیا.(۴) جَھَلَہٗ.اپنی حقیقت کو نہ سمجھا.(لسان) جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّمَا الْبَغْیُ مِنْ سَفْہِ الْحَقِّ اَیْ مِنْ جَھْلِہٖ (مسند احمد بن حنبل مسند عبد اللہ بن مسعودؓ) یعنی ظلم کسی کا حق نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے.اس جگہ سَفِہَ کے معنے حق کو
Page 493
بُھول جانے اور اس سے ناواقف ہوجانے کے ہیں پس بھولنا.بیوقوف بنانا.ہلاک کرنا.ناواقفی.عدم علم سب اس کے معنے ہیں.ان معنی کو مدّنظر رکھتے ہوئے آیت کے یہ معنے بنتے ہیں کہ (۱) جو شخص اپنی جان کو بھول جاتا ہے(۲) جو اپنی جان کو حماقت پر آمادہ کرتا ہے یا اپنے نفس کو کہتا ہے کہ تم بیوقوفی کرو.(۳) جو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے (۴) جو اپنے نفس کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتا.اِصْطَفٰی کے معنے ہیں اِخْتَارَ.اختیار کر لیا.پسند کر لیا.چن لیا.(۲) اَخَذَہٗ صَفْوَ ۃً اس کو پاکیزہ شکل میں لے لیا (المنجد)یعنی نہایت پسند یدہ صورت میں اسے اپنے قریب کر لیا.اور اس کے نیک اعمال دیکھ کر اُسے اپنے قرب میں جگہ دی.صَالِحٌ کے معنی ہیں درست.جس میں صلاحیت پائی جائے اور عمل صالح وہ عمل ہے جو مناسب حال ہو.نیک عمل اور ہوتا ہے اور مناسب حال اَور چیز ہے.نماز نیک عمل ہے مگر دشمن کے حملہ کے وقت وہ عمل صالح نہیں ہوتی بلکہ اس کے حملہ کا دفاع عمل صالح ہوتا ہے.پس صالح وہ شخص ہے جس کی زندگی اپنے ماحول کے مطابق ہو اور نیک بھی ہو.اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص صالح ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے اور مناسب حال کرتا ہے.بدی بھی کبھی مناسب حال ہوتی ہے مگر وہ نیکی نہیں ہوتی اس لئے وہ صالح نہیں ہوتی.صالح میں دونوں باتوں کی شرط ہے یعنی وہ خیر ہی خیر ہو اور پھر مناسب حال ہو.تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کرنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اس لئے پیش کی ہے کہ مخاطبین میں یہود اور نصاریٰ بھی شامل ہیں.اور ان کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ آپ پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے.لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اُن کے لئے دلیل ہو سکتی تھی کیونکہ عرب بھی اور یہودی بھی اور عیسائی بھی اور صابی بھی سب کے سب حضرت ابراہیم ؑ پر ایمان لانے میں مشترک تھے پس ضروری تھا کہ ان کے سامنے ایسے شخص کی مثال پیش کی جاتی جو علاوہ اہل عرب کے اہل کتاب کے تینوں گروہوں کے لئے بھی یکساں قابلِ احترام ہوتا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہو سکتے تھے.جو علاوہ عربوں کے یہود کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں.عیسائیوں کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں اور صابیوں کے لئے بھی واجب الاحترام ہیں.چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے عربو اور یہودیو اور عیسائیو اور صابیو! تم بھی ابراہیمی طریق اختیار کرو.اور جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حَکَم بن کر آیا ہے اس کو مانو او ر قومی جنبہ داریوں اور تعصبات کو چھوڑ دو.جیسا کہ ابراہیم
Page 494
نے خدا تعالیٰ کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا تھا.تب تمہارے لئے بھی یہ موقعہ پیدا ہو جائے گا کہ تم خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو.عربی زبان میں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں صرف عَنْ اور اِلٰی کے فرق سے بعض دفعہ ایک متضادمفہوم پیدا کر دیا جاتا ہے حالانکہ دوسری زبانوں میں اس کے لئے مستقل لفظ تلاش کرنا پڑتا ہے اس جگہ بھی یَرْغَبُ کے ساتھ عَنْ کا صلہ استعمال کر کے اسے اعراض کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے حالانکہ اِلٰی کے صلہ کے ساتھ اس کے معنے محبت اور پیار کے ہیں نہ کہ اعراض کے.درحقیقت اگر غور سے کام لیا جائے تو متضاد جذبات بھی ایک منبع سے تعلق رکھتے ہیں اور ظاہرمیں اُن کی جو ایک تبدیل شدہ شکل ہوتی ہے وہ حقیقت کا اختلاف نہیں بلکہ کیفیت کا اختلاف ہوتا ہے.رغبت اور نفرت بھی ایک ہی قسم کے جذبات ہیں.اسی طرح بہادری اور بزدلی بھی ایک ہی قسم کے جذبات ہیں صرف اُن کی کیفیت بدل جاتی ہے مثلاً رغبت کو ہی لے لو.جب انسان ایک چیز کی رغبت کرتا اور اس کی طرف جاتا ہے اور دوسری چیز کی طرف سے ہٹتا اور نفر ت کا اظہار کرتا ہے تو اگر ہم گہری چھان بین کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ان دونوں کے پیچھے ایک ہی جذبہ کام کر رہا ہوتا ہے جب انسان ایک چیز کی طرف جاتا ہے تو اس طرف جانے کا موجب بھی محبت ہوتی ہے اور جب کسی چیز کی طرف سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا موجب بھی ایک دوسری محبت ہوتی ہے گویا رغبت کا منبع بھی محبت ہے اور بے رغبتی کا منبع بھی محبت ہے.جب انسان ایک چیز کی طرف جاتا ہے تو وہ اس چیز کی محبت کی وجہ سے جاتا ہے اور جب کسی سے پیچھے ہٹتا ہے تو کسی اور چیز کی محبت کی وجہ سے ہٹتا ہے اسی طرح بہادری اور بُزدلی خواہش حفاظت کے تابع ہوتی ہے.جب انسان حملہ کرتا ہے تب بھی اس کی غرض جان بچاناہوتی ہے اور جب دشمن سے بھاگتا ہے تب بھی وہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے ہی بھاگتا ہے لیکن طریق مختلف ہیں ایک میں دوسرے پر حملہ کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اور دوسرے میں اپنے آپ کو ہٹا کر حفاظت کرنا چاہتا ہے.غرض عَنْ اور اِلٰیکے استعمال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت سے جذبات ایک ہی منبع کے تابع ہوتے ہیں صرف کیفیتوں کا اختلاف اور فرق ان میں پایا جاتا ہے.اِلَّا مَنْ سَفِہَ نَفْسَہٗ: سَفِہَ کے ایک معنے جیسا کہ حَلِّ لُغَات میں بتایا جا چکا ہے نَسِیَہٗکے ہیں اس لحاظ سے وَمَنْ یَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّۃِ اِبْرٰھٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِہَ نَفْسَہٗ کے یہ معنے ہوں گے کہ اس شخص کے سوا جو اپنے نفس کے فوائد کو کلی طور پر نظر انداز کر دیتا ہے.ابراہیم ؑ کے دین سے کون اعراض کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا طریق ترک کرنے سے نبیوں کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہاں انسان کی اپنی جان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے.ایک ظالم بادشاہ کو
Page 496
اُس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا اور برباد کر دیا.اس لحاظ سے اِس آیت کے یہ معنے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی مخالفت کرنے والے خواہ مشرکین مکہ ہوں یا یہود اور نصاریٰ انہیں یہ بات یاد رکھناچاہیے کہ اگر وہ دعائے ابراہیمی کے اِس مصداق کو قبول نہیںکریںگے اور بیت اللہ کے قیام کے مقاصد اور ہاجرہؓ اور اسما عیل ؑ کے مکہ میں قیام کی اصل غرض کو نظر اندازکر دیںگے تو وہ اپنی جان کو آپ ہلاک کرنے والے ہوں گے.یعنی اس لحاظ سے بھی اُن پر ہلاکت نازل ہو گی کہ وہ ہر قسم کی اعلیٰ تعلیم سے محروم رہیںگے اور اس لحاظ سے بھی ان پر ہلاکت نازل ہو گی کہ وہ خدائی عذاب میں گرفتار ہو ںگے جیسے ابو جہل نے تعلیم اسلامی پر عمل نہ کیا تو اُس پر خدا تعالیٰ کا فضل نازل نہ ہوا.یہ ایک طبعی نتیجہ تھا جو پیدا ہوا لیکن اس کے علاوہ ایک شرعی نتیجہ بھی اُس نے دیکھا اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے اُسے سزادی اور وہ جنگ بدر میں دو انصاری لڑکوں کے ہاتھوں نہایت ذلّت کے ساتھ ہلاک ہوا.(بخاری، کتاب المغازی ،باب قتل ابی جہل) سَفِہَ نَفْسَہٗکے چوتھے معنے جَھِلَہٗ کے ہیں.اِس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہیں کہ اُس شخص کے سوا جو اپنے نفس کو اعلیٰ درجہ کے حقائق سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے ملّتِ ابراہیمی سے کون اعراض کر سکتا ہے ؟ اِس میں یہ بتایا گیا ہے.کہ دعائے ابراہیمی کے نتیجہ میں جو عظیم الشان تعلیم دنیا کو ملی ہے یہ انسان کی اندرونی قابلیتوں کو اُبھار کر اُسے کامیابیوں کے اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے.اور سوائے ایسے شخص کے جو اپنے نفس کا دشمن ہوا ور اُسے اعلیٰ تعلیم سے باخبر رکھناپسند نہ کرتا ہواور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا.ہاں وہ شخص جو ترقی کی دوڑ میں کسی دوسرے سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا وہ اسے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا.کیونکہ اُس کے چھوڑنے سے نفس انسانی پر غفلت اور جمود کا طاری ہو جانا ایک لازمی امر ہے.جیسے موجود ہ زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کرنے والوں میں ایک عام جمود اور بے حسی پائی جاتی ہے.وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں.روزے بھی رکھتے ہیں.حج بھی کرتے ہیں.زکوٰۃ بھی دیتے ہیں.صدقہ وخیرات میں بھی حصّہ لیتے ہیں.مگر ہمیں خدا نہیں ملتا حالانکہ اُن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نمازمیں کھڑے ہو کر اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے تمام تر قیات کے دروازے بند ہیں.اور جب کسی انسان کا یہ خیال ہو تو اُسے نمازمیں وہ جوش کس طرح پیدا ہو سکتا ہے جو اُسے خدا تعالیٰ تک پہنچا دے.حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے.تو وہ کہتے ہیں.ابراہیمی انعامات میں ہم کہاں شریک ہو سکتے ہیں.حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں.اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام انہیں ملا وہ ہمیں کب مل سکتا ہے.حضرت اسحٰق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے.تو
Page 497
کہتے ہیں اُن کے انعامات ہمارے لئے کہاں مقدّر ہیں.حضرت موسیٰ.حضرت داؤد.حضرت سلیمان اور حضرت مسیح علیہم السلام کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو کچھ خدا نے انہیں دیاوہ ہمیں کب میّسر آسکتا ہے.غرض جب بھی وہ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیںتو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں مل سکتی.پھر اُن کے اندر دعا کے وقت جوش کس طرح پیدا ہو سکتا ہے.مگر ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اِس مقام پر پہنچایا ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ذکر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا وہ ہمیں بھی دے سکتا ہے اور ہمارے لئے بھی وہ مراتب قرب کھلے ہیں جو پہلے لوگوں نے حاصل کئے.اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہمیں ملتے ہیںوہ اُن کو نہیں ملتے.غرض مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعہ جو تعلیم دنیا میں آئی ہے وہ انسانی قوتوں کو اُبھارنے والی اور اُس کے نفس کو ترقیات کے بلند مینار تک لے جانے والی ہے.وہ یہ نہیں کہتی کہ انسان گنہگار پیدا ہوا ہے.بلکہ کہتی ہے کہ انسان فطرتاً نیک پیدا ہوا ہے اور نیکی میں ترقی کرنے کیلئے پیدا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ میں اور نیکیاں کروں اورخدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھ جاؤں لیکن جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انسان گنہگار پیدا ہوا ہے تو پھر انسان مردہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نیک عمل کی کیا ضرورت ہے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اس تعلیم کو چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تعلیم بڑی فوائد والی ہے اور اس سے وہی شخص اعراض کرسکتا ہے جو اپنے نفس کے حقوق پہچاننے سے بھی عاری ہو.اِصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں صفوۃ اور بزرگی بخشی تھی وہ خدا تعالیٰ کا چنیدہ بندہ تھا.اُسے دوسروں پر فضیلت حاصل تھی اورخدا تعالیٰ کا قرب نصیب تھا.وَ اِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ اورآخرت میں بھی وہ یقیناً اُن بندوں میں شمار ہو گا جو جنتی زندگی کے مناسب حال اعمال بجالانے والے ہوں گے.اِس سے صاف طور پر یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جنّت میں بھی عمل ہے اور وہ ایسا مقام نہیں جیسا کہ مسلمان اس کا عام طور پر نقشہ کھینچا کرتے ہیں کہ وہاں ہر شخص بیکار بیٹھا ہو ا رات دن کھانے پینے میں مشغول رہےگا.اگر ایسا ہوتا تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہاں اتنی حوریں ملیں گی.اتنے باغ ملیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا.بلکہ اسکی بجائے وَاِنَّہٗ فِی الْاٰخِرَۃِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ فرمایا ہے.جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے جہان میں بھی نیک عمل ہوگا.ورنہ کیا کوئی شخص یہ تصوربھی کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلے جہان میں نعوذ باللہ بے نماز ہوں گے.یا وہاں اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنے کا احساس اُن کے دل میں نہیں
Page 498
رہےگا.پس وہاں بھی عمل ہو گا اور جنتیوں کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازے اُسی طرح کھلے ہوں گے جس طرح اس جہان میں کھلے ہیں.اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ١ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۰۰۱۳۲ جب اس کے ربّ نے اسے کہا کہ (ہماری) فرمانبرداری اختیار کر.اس نے (جواب میں ) کہا کہ میں تو (پہلے ہی سے) تمام جہانوں کےربّ کی فرمانبرداری اختیار کر چکا ہوں.حَلّ لُغَات.اَسْلَمَ کے معنے ہیں.اِنْقَادَ.مطیع ہو گیا.(۲) تَدَیَّنَ بِدِیْنِ الْاِسْلَامِ.اس نے دین اسلام اختیار کر لیا.(۳) اَسْلَمَ اَمْرَہٗ اِلَی اللّٰہِ اُس نے اپنا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دیا (اقرب).پس اَسْلَمَکے معنے ہیں سپرد کردینا.تفسیر.عربی زبان میں اَسْلَمَکے ساتھ اِلٰی کا صلہ استعمال ہوا کرتا ہے.لیکن یہاں اِلٰی کی بجائے لامکا صلہ استعمال کیا گیا ہے.مفسرین خیال کرتے ہیںکہ اس جگہ لام کا صلہ اِلٰی کا قائم مقام ہے.لیکن میرے نزدیک یہ درست نہیں.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا تعالیٰ کے حکم اَسْلِمْ کے جواب میں اَسْلَمْتُ کہا تو یہ مضمون تو اس میں خود بخود آگیا کہ میں خدا تعالیٰ کا فرمانبردار ہوچکا ہوں کیونکہ انہوں نے خدا تعالیٰ کا ہی فرمانبردار ہونا تھا کسی اور کا نہیں.پس یہاں لام کا صلہ استعمال کرنے کی یہ وجہ نہیں کہ وہ خد ا تعالیٰ کے متعلق اپنی فرما نبرداری کا اظہار کرنا چاہتے تھے.بلکہ درحقیقت اس میں اَسْلَمْتُ کہنے کی انہوں نے یہ وجہ بتائی ہے اور کہا ہے کہ میں اپنے کام خدا تعالیٰ کو اس لئے نہیں سونپتا اور اس وجہ سے اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا کہ مجھے کوئی مادی نفع حاصل ہو.بلکہ میں ربُّ العالمین خدا کی خاطر ایسا کرتا ہوں.تاکہ وہ مجھے مل جائے کیونکہ وہ میرا اور سب جہان کا محسن ہے اور میں اس سے جدُا رہنا پسند نہیں کرتا.گویا یہ ایک زائد مضمون ہے.جو انہوں نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے.انہیں یہ حکم ہوا تھاکہ اَسْلِمْ یعنی اے ابراہیم !میں تجھے صرف یہی نہیں کہتا کہ تو کسی بُت کو سجدہ نہ کر بلکہ میں تجھے یہ بھی کہتا ہوں کہ تو اپنے دل کے خیالات بھی کلّی طور پر میری اطاعت میں لگا دے اور ابراہیم ؑ نے اس کے جواب میں فورا ً کہا کہ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.اے خدا ! میرے جسم کا ذرّہ ذرّہ تیرے آگے قربان ہے.میری عقل اور میرا علم اور میرا ذہن سب تیرے احکام کے تابع ہیں.اور میری ساری طاقتیں اور ساری قوتیں ربُّ العالمین
Page 499
خدا کی راہ میں لگی ہوئی ہیں.گویاانہوں نے بتایا کہ میری زندگی اپنے ذاتی مفاد کیلئے نہیں بلکہ ساری دنیا کیلئے وقف ہے.اور ربُّ العالمین خدا کی مظہریت میں ساری مخلوق کی شفقت میرے پروگرام میں شامل ہے.اور میں اسے کبھی فراموش نہیں کرونگا.میں صرف اپنے لئے بھلائی نہیں مانگوںگا بلکہ ساری دنیا کےلئے بھلائی مانگوں گا.اور ساری دنیا کی بہبودی ہمیشہ اپنے مد نظر رکھو ںگا.گویا انہوں نے اَسْلِمْکے جواب میں اَسْلَمْتُ کہہ کر ایک تو اس طرف اشارہ کیا کہ میرے تو جسم اور روح کا ذرّہ ذرّہ پہلے ہی حضور کی راہ میں قربان ہے.حضور مجھ سے جو چاہیں معاملہ کریں اور پھر لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کا اضافہ کر کے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے آپ کو صفت ربُّ العالمین کے ماتحت ساری دنیا کیلئے وقف کر دیا ہے.چنانچہ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ کا مقام حاصل ہونے کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ دعا مانگی کہ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ چونکہ اُن کی اپنی بعثت تمام دنیا کی طرف نہیں تھی اِس لئے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ الٰہی آئندہ دنیا میں ایک عظیم الشان رسول کھڑا کیجئے اوروہ رسول میری اولاد میں سے ہو تاکہ ساری دنیا کی بھلائی ہو اور ربُّ العالمین کی تمام مخلوق اُس کے فیض سے مستفیض ہو.وَ وَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ١ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اور ابراہیم ؑ نے اپنے بیٹوں کو اور( اسی طرح) یعقوب ؑ نے بھی (اپنے بیٹوں کو) اس بات کی تاکید کی (اور کہا کہ) اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَؕ۰۰۱۳۳ کہ اے میرے بیٹو!اللہ نے یقیناً اس دین کو تمہارے لئے چن لیا ہے.پس ہرگز نہ مرنامگر اس حالت میں کہ تم (اللہ کے) پورے فرمانبردار ہو.تفسیر.فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور ابراہیم ؑ کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اِس بات کی تاکید کی تھی کہ تم اپنی خیرخواہی صرف اپنی ذات یا اپنی قوم تک محدود نہ رکھنا بلکہ اُسے وسیع کرتے چلے جانا اور ساری دنیا کو اِس میں شامل کرنا.اس جگہ دین سے مراد وہی لائحہ عمل ہے جس میں تما م جہان کی بہتری مدّ نظر ہو.گویا ابراہیم ؑ نے اپنے پڑپوتوں تک کو ہدایت دی کہ اپنے آپ کو صفت ربُّ العالمین کا مظہر بنانا اور دنیا کی کسی قوم کو اپنی خیر خواہی سے محروم نہ رکھنا.فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ کے دو۲ معنے ہیں.ایک یہ کہ ہر وقت اسلام پر قائم رہو.کیونکہ موت کے متعلق
Page 500
کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کب آجائے.اس لئے تمہارا فرض ہے کہ ہمیشہ ربّ العالمین کے فرمانبردار رہو.اور خدا تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرو.تاکہ جب موت آئے تو وہ تمہیں اطاعت کے سوا اور کسی حالت میں نہ پائے.دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بڑھاؤکہ وہ تمہاری تباہی کو برداشت ہی نہ کر ے.اور اُسوقت تم کو موت دے جبکہ تم کامل مومن بن چکے ہواور اس کی خوشنودی حاصل کر چکے ہو.قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان پر قبض اور بسط کی حالت آتی رہتی ہے.کبھی تو انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ دنیا جہاں کو بھلا دیتا ہے اور کبھی دوسری چیزوں کی طرف اُسے اتنی توجہ ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے.چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کس طرح؟ اُس نے کہا.یا رسول اللہ! میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میری اور حالت ہوتی ہے اور جب میں گھر جاتا ہو ںتواور حالت ہوجاتی ہے.آپ نے فرمایا.یہ کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں.اگر ہر وقت ایک جیسی حالت رہے تو انسان مر جائے (ابن ماجہ ابواب الزھد باب المدوامة علی العمل).دراصل قبض اور بسط کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں.کامل مومن کی جو حالت قبض ہوتی ہے وہ اس سے نچلے درجے والے کےلئے بسط کی حالت ہوتی ہے.اِسی طرح انبیاء پر بھی قبض و بسط کا دور آتا رہتا ہے مگر نبیوں کی قبض صدیقوں کی بسط ہوتی ہے.اِسی لئے صوفیاء نے کہا ہے کہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَیِّئَاتُ الْمُقَرَّ بِیْنَ یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقربین کی بدیاں ہوتی ہیں.اس کا یہی مطلب ہے کہ اوسط درجہ کے لوگ جس کو نیکی سمجھتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے نزدیک بعض دفعہ بدی بن جاتی ہے اور اوسط درجہ کے لوگوں کی بدیاں ادنیٰ درجہ کے لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں.پس چونکہ یہ دو۲ حالتیں انسان پر آتی رہتی ہیںاور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں.اس لئے فرمایا کہ تم خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق بڑھاؤ کہ تم پر موت ایسے وقت میں آئے جو تمہارا بہترین وقت ہو اور ملک الموت تمہاری اسوقت جان نکالے جب تمہارا خدا تعالیٰ سے ایک سچا اور مخلصانہ تعلق قائم ہو چکا ہو.
Page 501
اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ١ۙ اِذْ قَالَ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت (کی گھڑی) آئی.(اور) جب اس نے لِبَنِيْهِ مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِيْ١ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ؟ انہوں نے (جواباً) کہا کہ ہم تیرے معبود اِلٰهَ اٰبَآىِٕكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا١ۖۚ وَّ اور تیرے باپ دادوں ابراہیم ؑ اوراسمٰعیل ؑ اور اسحاق ؑ کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے عبادت کریں گے نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ۰۰۱۳۴ اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں.حَلّ لُغَات.اَ لْاَبُ: اَلْوَالِدُ.وَیُسَمَّی کُلُّ شَیْ ءٍ مَنْ کَانَ سَبَبًا فِیْ اِیْجَادِشَیْ ءٍ اَوْاِصْلَا حِہٖ اَوْ ظُھُوْرِہٖ اَ بًا(مفرداتِ راغب) یعنی اَبٌ والد کو کہتے ہیں.اسی طرح ہر وہ چیز جو کسی چیز کے پیدا کرنے یا اصلاح کرنے یا ظاہر کرنے کا موجب ہو اُسے بھی اَبٌ کہتے ہیں.اور جب چچا کا باپ کے ساتھ ذکر کیا جائے تو چچا بھی اَبٌ کہلاتاہے.اِسی طرح ما ں باپ کیلئے اَبْوَیْن آتا ہے.اور دادا اور باپ کا ذکر ہو تو بھی اَبْوَیْن کہتے ہیں.غرض ماں بھی اَبٌ اورچچا بھی اَبٌ اور دادا بھی اَبٌ کہلاتا ہے.تفسیر.حَضَرَ یَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ایک محاورہ ہے جو جان کندنی کےلئے نہیں بلکہ موت کے قریب آجانے کےلئے استعمال ہوتا ہے.ورنہ جان کندنی کے وقت تو انسان کلام ہی نہیں کر سکتا.جب غرغرہ موت شروع ہو جاتا ہے تو انسان کے حواس پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے گو وہ بھی کبھی زیادہ لمبا اور کبھی بہت قلیل عرصہ کے لئے ہوتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ جان کندنی تک قبول ہوتی ہے (ترمذی ابواب الدعوات باب فی فضل التوبة وا لاستغفار).جب جان کندنی شروع ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی.کیونکہ جب غرغرہ موت شروع ہوجاتا ہے تو حواس جاتے رہتے ہیں.یہ غرغرہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے.ایک ابتدائی اور ایک اُس کے بعد کا جو اصلی اور حقیقی ہوتاہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بڑے طاقتور تھے.
Page 502
غرغرہ موت شروع ہوا تو فرمانے لگے.غلام احمد یہ غرغرہ ہے اور پھر چند منٹ کے بعد فوت ہو گئے.تو حَضَرَ یَعْقُوْبَ الْمَوْتُ سے مراد جیسا کہ بعض نے سمجھا ہے یہ نہیں کہ جب جان کندنی شروع ہو گئی تھی.بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اُن کی موت کا وقت قریب آگیا تھا.اِذْقَالَ یہ پہلے اِذْ کا بدل ہے.گویا حَضَرَ الْمَوْتُ سے مراد وہ وقت ہے.جب انہوں نے موت کو قریب دیکھتے ہوئے وصیت کی.اور اپنی اولاد سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کروگے ؟ قَالُوْ انَعْبُدُ اِلٰھَکَ وَاِلٰہَ اٰبَآ ءِ کَ.اس آیت پر عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت اسماعیل ؑ تو اُن کے آباء میں سے نہ تھے.بلکہ چچا تھے.پھر انہیں اَبٌ کیوں کہا گیا ہے.؟ مگر یہ اعتراض اُن کی عربی زبان سے ناواقفیت کا ثبوت ہے.عربی زبان میں اَبٌ کا لفظ چچا کیلئے بھی استعمال ہو سکتا ہے.لیکن چونکہ عیسائی جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اُن کی نیّت صرف اعتراض کرنا ہوتی ہے.اس لئے وہ بات بات پر اعتراض کرنا شروع کردیتے ہیںاور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے ان کی اپنی نا بینائی کا ثبوت ملتا ہے.یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے نَعْبُدُ اِلٰھَکَ کہہ د یا تھا تو پھر اِلٰهَ اٰبَآىِٕكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا کہنے کی کیاضرورت تھی کیونکہ جو یعقوبؑ کا معبود تھا وہی ابراہیم ؑ کا معبود تھا.وہی اسمٰعیل ؑ اور اسحاق ؑ کا تھا.پس اِلْھَکَ پر اکتفاء نہ کرتے ہوئے اِلٰـہَ اٰبَآئِکَ کہنا اور پھر اس پر بھی اکتفا نہ کرتے ہوئے ابراہیم ؑ اسمٰعیل ؑ اور اسحاق ؑ کے الفاظ بڑھانا کیا معنے رکھتا ہے.سو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الوراء ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی.ہم ربؔ.رحمٰنؔ اور رحیمؔ وغیرہ الفاظ تو استعمال کر لیتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کی پوری حقیقت صرف ان چند الفاظ سے واضح نہیں ہوتی اور جب انسان یہ چاہتا ہو کہ وہ کسی بات کو کھول کر بیان کرے تو اس کی وضاحت کے لئے مختلف طریق اختیار کرتا ہے.جیسے اگر انسان اپنے کسی محسن کا احسان یاد دلائے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر احسان ہے اور پھراُس کی تشریح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اُس نے کیا احسان کیا.اِسی طرح اللہ تعالیٰ کے جلال اور اُس کے جمال کا اظہار مختلف تجلیات میں ہوتا ہے.کوئی تجلی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی.کوئی تجلی حضرت اسحاق علیہ السلام پر ہوئی.کوئی تجلی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر ہوئی.پس اُن کی اولاد نے ضروری سمجھا کہ وہ اپنے اُن آباء کا نام لے کر کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات سے خوب آگاہ ہیں جو اُن کے وجود سے ظاہر ہوئیں.ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی دیکھی ہے اور خدا تعالیٰ کی وہ تجلی بھی دیکھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہوئی تھی اسی طرح ہم نے وہ تجلی بھی دیکھی ہے جو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام پر ظاہر
Page 503
ہوئی تھی.پھر حضرت اسحاق علیہ السلام والی تجلی سے بھی ہم ناواقف نہیں.اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اپنے تفصیلی علم کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ کیا اتنے جلوے دیکھنے کے بعد بھی ہم بے ایمانی کر سکتے ہیں یہ ویسی ہی بات ہے جیسا کہ ہندہ کے متعلق فتح مکہ کے موقعہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ وہ جہاں ملے اُسے قتل کر دیا جائے.کیونکہ اس نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کروایا تھا مگر وہ عورت ہوشیار تھی چالاکی سے عورتوں میں مل کر بیعت کرنے کے لئے آگئی.جب آپؐ نے عورتوں سے فرمایا کہ کہو ہم شرک نہیں کریں گی تو وہ فوراً بول اُٹھی کہ یا رسول اللہ! کیا اب بھی ہم شرک کریں گی آپ اکیلے تھے اور آپ کے مقابلہ پر تمام عرب تھا.ہم نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو ناکام بنانے کے لئے ایڑی سے چوٹی تک زور لگایا مگر اس کے باوجود آپ کامیاب ہو گئے اور ہمارے بتوں نے ہماری کچھ بھی مدد نہ کی.کیا اتنے واضح نشان کے بعد بھی ہم شرک کریںگی(تاریخ طبری سنة ۸ فتح مکة).حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے بھی یہی جواب دیا.چونکہ ان کے ایک حصّہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت کر کے عدمِ ایمان کا ثبوت دیا تھا.اور پھر مصر میں بُت پرستی بھی عام تھی اس لئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اُن سے آخری وقت میں پوچھا کہ میری زندگی میں تم میری پیروی کرتے رہے لیکن اب بتائو کہ میرے مرنے کے بعد تم کیا رویہ اختیار کرو گے.انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان اب پختہ ہو چکا ہے اور ہم پر تمام تجلیات ظاہر ہو چکی ہیں اب ہم خدا تعالیٰ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں وہ نادانی کا وقت اور تھا جبکہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی مخالفت کی اور اُن کو کنوئیں میں ڈال دیا تھا.اب ہم سے یہ حماقت نہیں ہو سکتی.اِلٰهًا وَّاحِدًا.اِلٰہَ اٰبَآئِکَ کا بدل ہے چونکہ انہوں نے مختلف ناموں یعنی ابراہیم ؑ.اسماعیل ؑ اور اسحٰق ؑ کی طرف اِلٰہکو منسوب کیا تھا اس لئے خیال ہو سکتا تھا کہ شاید کئی اِلٰہ ہوں اس شبہ کے ازالہ کے لئے بتایا کہ وہ ایک ہی خدا ہے.اِلٰـھًا وَّ احِدًا حال بھی ہو سکتا ہے یعنی حَالَ کَوْنِہٖ اِلٰھًا وَّ احِدًا اس حال میں کہ ایک ہی خدا ہے صرف اس کی تجلّیات مختلف ہیں.درحقیقت اس میں یہود کو توجہ دلائی گئی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو مرتے وقت بھی ایک خدا کی پرستش کی تاکید کرتے گئے ہیں پھر اُن کی نسل آج اپنی ہواوہوس کے پیچھے کیوں پڑرہی ہے.وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک ہر سچا پرستار مسلم ہے.چنانچہ پہلے کہا تھا.وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ اور اس جگہ انہوں نے خود کہا ہے وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ.حالانکہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر دین کا سچا پرستار مسلم ہے اور اسی بنا پر تمام پہلے مذاہب کے پیرو جو اپنے اپنے مذہب کی تعلیم پر سچے دل سے عمل کرنے والے تھے وہ بھی مسلم
Page 504
ہی تھے کیونکہ جو بھی خدااور اس کے نبی پر ایمان لاتا ہے.وہ مسلم بن جاتا ہے مگر ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ اُن کا نام مسلم نہ تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی اُمت کے لوگ مسلم نام سے پکارے جاتے ہیں.پہلی امتوں کے افراد بے شک اطاعت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے مسلم تھے مگر لفظ مسلم نام کے طور پر وہ استعمال نہیں کرتے تھے.اور نہ اس نام سے وہ پکارے جاتے تھے.لیکن اس اُمت کے لوگ اس نام سے پکارے جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے مذاہب منسوخ ہونے والے تھے لیکن اسلام نے کبھی منسوخ نہیں ہونا تھا.پس اس کو یہ نام دیا گیا تاکہ گڑبڑ واقع نہ ہو.اور اُسی مذہب کے پیرو مسلم کہلائیں جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے.حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جب کوئی نام دیتا ہے تو اُس وقت دیتا ہے جب اُس نے ہمیشہ کے لئے قائم رہنا ہو.جیسے کسی نبی کا پہلے کوئی کلمہ نہیں ہو تا تھا مگر محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلمہ بھی دیا گیا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں نے بہت سے کلمے بنا لئے ہیں جیسے لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ عِیْسٰی رُوْحُ اللّٰہ یا لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اٰدَمُ صَفِیُّ اللّٰہِ یا لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُوْسٰی کَلِیْمُ اللّٰہِ اور پھر اس کے لئے انہوں نے کوئی نہ کوئی روایت بھی گھڑ لی ہے.مگر درحقیقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کے آخری نبی تک کوئی کلمہ نہ تھا صرف وہی کلمہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے.کیونکہ اگر پہلے خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی نبی کا نام لگایا جاتا اور پھر اُسے ہٹایا جاتا تو یہ بے ادبی ہوتی.پس صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگایا گیا کیونکہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نے قیامت تک چلنا تھا.غرض اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جس چیز نے مٹ جانا ہو اُسے نام نہیں دیا جاتا.چونکہ اس امت نے قیامت تک رہنا تھا اس لئے اسے مسلم نام دے دیا گیا.اسی طرح آپ کی تعلیم کو بھی ایک نام دے دیا گیا یعنی قرآن.پہلی کتابوں مثلاً تورات اور انجیل وغیرہ کا نام خدا تعالیٰ نے نہیں رکھا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا نام قرآن خود خدا نے رکھا ہے.غرض خدا تعالیٰ خود اپنی طرف سے اُن کو نام دیتا ہے جنہوں نے قائم رہنا ہوتا ہے.پس معنوی لحاظ سے تو وہ سب لوگ مسلم تھے جو پہلی اُمتوں میں ہوئے مگر جہاں تک مسلم نام کا تعلق ہے خدا تعالیٰ نے یہ نام صرف اس اُمت کو دیا ہے کیونکہ یہ قیامت تک رہنے والی تھی.انجیل اور تورات لوگوں کے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں اور انہی ناموں سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اُن کا ذکر کیا ہے.اس بات سے کہ قرآن کریم میں ان کے یہ نام آئے ہیں.یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ نے اُن کے یہ نام رکھے تھے.جیسے قرآن کریم نے زید کا بھی نام لیا ہے مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کا نام خدا تعالیٰ نے رکھا تھا وہ تو اس کے ماں باپ نے ہی رکھا تھا مگر خدا تعالیٰ نے بھی وہی نام لیا.کیونکہ اسی
Page 505
نام سے وہ مشہور تھا.پھر سابق مذاہب کے پیروؤں کو اس وجہ سے بھی مسلم کا نام نہیں دیا گیا کہ نام پانے کا مستحق کامل مذہب ہی ہوتا ہے پس جب وہ مذہب بھیجا گیا جو اپنے کامل ہونے کی وجہ سے تمام مذاہب سے افضل تھا تو اس کا نام بھی اسلام رکھ دیا گیا.تاکہ اس کا نام ہی اس کی غرض وغایت پر روشنی ڈالنے کے لئے کافی ہو.وہیری ایک عیسائی مفسرہے وہ اعتراض کرتا ہے کہ اس آیت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے لوگ بھی میرے دین کے تابع تھے چنانچہ نَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ سے وہ استنباط کرتا ہے کہ یعقوبؑ کی اولاد نے کہا کہ ہم محمدؐ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر بہت سے دلائل سے اس بات کو ردّ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بالکل غلط ہے.مگر دراصل وہیری کو دھوکا لگا ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ اُنہی تفاصیل کے پابند تھے جو اسلام میں پائی جاتی ہیں بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں سچے دین کے پیرو تھے اور اس سے کوئی سلیم العقل انسان انکار نہیں کر سکتا.ورنہ نام کے طور پر یہ لفظ صرف امتِ محمدؐ یہ کو ملا ہے اور کسی کو نہیں.اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی یا نہیں؟ اور اگر کی تھی تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس بارہ میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہم اس کا تورات سے ثبوت پیش کریں.یہ تو عقلی بات ہے کہ ہر راستباز اپنی اولاد کو اس قسم کی نصیحتیں کرتا اور اُن پر عمل کرنے کی تاکید کیا کرتا ہے.خصوصاً موت کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرنا تو ایک ایسی عام بات ہے جس کا نظارہ ہمیں لاکھوں آدمیوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لئے تو یہ بات اور بھی ضروری تھی کیونکہ وہ حصہ جو ٹھوکر کھا چکا ہو اس کے متعلق والدین کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ اُسے نصیحت کی جائے پس یہ ایک فطری بات ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا لیکن اگر انہوں نے وصیت کی بھی تھی تو سوال یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل نے بائیبل میں یہ وصیت رہنے دینی تھی؟ جن لوگوں کو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام سے اتنا بغض ہے کہ راستہ چھوڑ کر بھی اُن کی عیب جوئی کر لیتے ہیں اگر اُن کا ذکر آجاتا تو انہوں نے اُسے کہاں رہنے دینا تھا مگر باوجود اِس کے کہ اُن کی کُتب انسانی دست بُرد سے محفوظ نہیں.اس وصیت کے کچھ کچھ نشان ہمیں مل جاتے ہیں اور یہ نشان بھی خود عیسائیوں نے مہیا کیا ہے.کئی عیسائیوں نے قرآن کریم کے ترجمے کئے ہیں.اُن میں سے ایک مترجم راڈول بھی تھا.اُس نے اپنے مترجم قرآن کریم میں اس آیت کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مدراش ربّاہ میں جو طالمود کا حصّہ ہے پیدائش باب۴۹ آیت۲ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ
Page 506
’’اُس وقت کہ ہمارے باپ یعقوب نے اس دنیا کہ چھوڑا اُس نے اپنے بارہ بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اُن سے کہا.اپنے باپ اسحٰق کی بات کو سُنو.کیا تمہارے دلوں میں قدّوس خدا کے متعلق کوئی شبہ ہے ؟ انہوں نے کہا سُن اے اسرائیل ہمارے باپ جس طرح تیرے دل میں کوئی شبہ نہیں اسی طرح ہمارے دل میں بھی نہیں.کیونکہ وہ آقا ہمارا خدا ہے اور وہ ایک ہے.‘‘ (MIDS RABBAH ON GENESIS PAGE98.DEUT PARA 2 ترجمۃ القرآن راڈویل زیر آیت ھٰذا) پس حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو جمع کرنا اور انہیں نصیحت کرنا اور پھر ان کا اقرار کرنا ثابت ہے گو اس کی ساری تفصیل نہیں.اور یہی فرق ہے جو قرآن کریم کی عظمت کو دوبالا کرتا ہے.قرآن کریم۱۹۰۰ سال کے بعد نازل ہو کر صحیح تفصیل بیان کر دیتا ہے مگر بائیبل اپنے زمانہ کی بھی صحیح تفصیل نہیں بتاتی.تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ١ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ١ۚ یہ وہ جماعت ہے جو (اپنا زمانہ پورا کر کے) فوت ہو چکی ہے.جو کچھ اس نے کمایا (اُس کا نفع نقصان) اس کے لئے ہے اور جو کچھ تم نے کمایا وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۰۰۱۳۵ (اُس کا نفع نقصان)تمہارے لئے ہےاور جو کچھ وہ کرتے تھے اُس کے متعلق تم سے (کچھ) نہیں پوچھا جائے گا.حَلّ لُغات.خَلَا کے معنے گذر جانے کے ہوتے ہیں(مفرداتِ راغب) چنانچہ خَلَا الزَّ مَانُ کے معنے ہیں مَضٰی یعنی زمانہ گذر گیا.آگے محاورہ میں اِس کے معنے مَاتَ کے بھی آتے ہیں.خَلَتْ: مَاتَتْ.اِنْقَضَتْ وَسَارَتْ اِلَی الْخَلَاءِ وَھُوَ الْاَرْضُ الَّتِیْ لَا اَنِیْسَ فِیْھَا.(لسان) یعنی خَلَتْ کے معنے ہیں مر گیا اور ایسی زمین میں چلا گیا جہاں اُس کا کوئی انیس اور غم خوار نہیں.تفسیر.عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے اعمال ہمارے کام آجائیں گے اگر وہ نیک اور پارسا تھے تو ہم بھی اُن کی اولاد ہونے کی وجہ سے انہی کے ساتھ جگہ پائیں گے.اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس خیال کی تردید فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ اُن کے اعمال اُن کے ساتھ ہیںاور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ.تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیسے اعمال کرتے تھے.بلکہ یہ سوال ہو گا کہ تم کیا کرتے رہے.اگر یہ سوال ہونا ہوتا کہ تمہارے باپ دادوں نے کیا کیا تھا تو شاید تم بچ جاتے مگر سوال تو یہ ہو گا کہ تم نے کیا کیاہے.
Page 507
چنانچہ لَھَا مَاکَسَبَتْ میں یہی بتایا ہے کہ اُن کی نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیںگی اور تمہاری بدیاں اُن کے ذمہ نہیں ڈالی جائیں گی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضرت ابراہیم.اسمٰعیل اور اسحاق علیہم السلام نے کیا کیا تھا بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا.وَ لَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَکا یہ مطلب نہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا بلکہ یہ مطلب ہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیانیکیاں کی تھیں بلکہ تم سے صرف تمہارے ذاتی اعمال کے متعلق سوال ہو گا.اس لئے اپنے اسلاف کے عمل پر اپنی نجات کو منحصر نہ سمجھو.وَ قَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا١ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اور (کیا تم نے سنا کہ) وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی یا مسیحی ہو جائو (اس طرح) تم ہدایت پا جائو گے.تو (اُن سے) کہدے اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا١ؕ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۰۰۱۳۶ (کہ یوں) نہیں بلکہ ابراہیم کے دین کو جو (خدا ہی کی طرف) جھکنے والا تھا (اختیار کرو) اور (یاد رکھو کہ) وہ مشرکوں میں سے نہ تھا.حَلّ لُغَات.اَلْحَنِیْفُ کے معنے ہیں اَلْمَائِلُ عَنِ الشَّیْ ءِ کسی چیز کی طرف سے توجہ پھیر کر دوسری طرف جُھک جانے والا.محاورہ۲ میں اس کے معنے ہیں اَلْمَائِلُ عَنِ الضَّلَا لَۃِ اِلَی الْھُدیٰ(مفردات)جو شخص ضلالت کی طرف سے منہ پھیر کر ہدایت کی طرف توجہ کرے.(۳) اَلْمُسْتَقِیْمُ.سیدھا (اقرب الموارد) (۴) اَلصَّحِیْحُ الْمَیْلَانِ اِلَی الْاِسْلَامِجس کی اسلام کی طرف صحیح توجہ ہو.پس حنیف کے معنے ہیں.ضلالت چھوڑنے والا صحیح راستہ پر چلنے والا.اسلام کی طرف صحیح رغبت رکھنے والا.اور اس کے ایک معنے قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتے ہیں کہ جو سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو.کیونکہ اس کے معًا بعد یہ ذکر آتا ہے کہ قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَاۤ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ١ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ١ۖٞ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.گویا حنیف کی تشریح یہ ہے کہ جو سب رسولوں پر ایمان لائے.ابنِ کثیر میں ابوقلابہ کا بھی ایک قول آتا ہے کہ اَلْحَنِیْفُ الَّذِیْ یُوْمِنُ بِالرُّسُلِ کُلِّھِمْ مِنْ اَوَّ لِھِمْ اِلیٰ اٰخِرِھِمْ.(تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان زیر آیت ھذا) یعنی حنیف وہ ہے جو سب رسولوں پر ایمان لائے.انہوں نے معلوم نہیں
Page 508
کہاں سے استدلال کیا ہے مگر میں نے اس سے اگلی آیت سے استدلال کیا ہے کیونکہ اگلی آیت میں حنیف ہی کی تشریح ہے اور تمام رسولوں کے ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے.تفسیر.فرماتا ہے یہود کہتے ہیں کہ یہودی بننے میں نجات ہے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسائی بننے میں نجات ہے مگر دونوں کی بات غلط ہے.اصل بات یہ ہے کہ نہ یہودی کہلانے سے کام بنے گا نہ نصرانی کہلانے سے.بلکہ ابراہیمی ملّت کی پیروی کرنے سے نجات ہو گی.یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ابراہیمی کہلانے سے نجات ہو گی کیونکہ یہ پھر ویسی ہی بات ہو جاتی جیسی انہوں نے کہی تھی اس لئے فرمایا کہ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ہدایت کا راستہ اختیار کرے.یہی طریق ابراہیمؑ کا تھا جو ہر وقت خدا کے حکموں کی طرف کان لگائے رکھتا تھا.محض یہودی یا عیسائی کہلانے سے کچھ نہیں بن سکتا.اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں ان سب کے پیروؤں میں اپنے تنزّل کے زمانہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اسی مذہب میں شامل ہو کر نجات میسر آسکتی ہے لیکن یہ ایک غلط خیال ہے.نجات کا اصلی باعث فضل ِ الہٰی ہوتا ہے اور فضل الہٰی کو جذب کرنے کا ذریعہ اطاعت ِ الہٰی ہے.پس جب تک کسی سچے مذہب میں شامل ہو کر اطاعت ِ الہٰی ہو اُس وقت تک تو اس میں نجات کا امکان ہے.لیکن جب اطاعت نہ ہوتی ہو تو کوئی نجات نہیں.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود اور نصاریٰ کو جو زور دیتے ہیں کہ ہدایت پانا چاہو تو ہمارے مذہب میں داخل ہو جائو پھر ڈانٹا ہے کہ کیا کسی مذہب کا نام لینے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے ؟ نجات حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ ملّت ابراہیم کی اتباع کی جائے اور ابراہیم ؑ کا طریق یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم بھی ملا.انہوں نے اُس کو قبول کر لیا.یہی دین ابراہیم ؑ ہے.اور اسی کی پیروی ہر اس قوم پر فرض ہے جو ابراہیم ؑ کی بزرگی کی قائل ہے.حنیف کے معنے جیسا کہ اوپر بتا یا جا چکا ہے ایسے شخص کے ہیں جو ضلالت سے منہ موڑ کر ہدایت اور راستی کی طرف جھکا ہوا ہو.اسی طرح حنیف اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو اسلام کا کلّی طور پر والہ و شیدا ہو اور اس کی طرف اپنی تمام تو جہات کو مرکوز رکھتا ہو.اور ابو القلابہ نے جو ایک بہت بڑے مفسر اور تابعین میں سے ہیں حنیف کے معنے ایسے شخص کے کئے ہیں جو اول سے آخر تک تمام انبیاء پر ایمان لائے اور کسی ایک کا بھی انکار نہ کرے.پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دے کر بتایا گیا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری کے لحاظ سے ایک ایسے مقام پر فائز تھے کہ ضلالت کی طرف ایک معمولی میلان بھی اُن کے تصوّرات سے بالا تھا.اور خدا تعالیٰ کے احکام کی کامل اطاعت اور فرمانبرداری اُن کا شیوہ تھا اس کے بعد فرمایا وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.ابراہیم ؑ مشرکوں
Page 509
میں سے نہ تھے.حنیف کے ساتھ ان الفاظ کی زیادتی اس حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لئے کی گئی ہے کہ جو شخص الہام اور نبوت و رسالت کے سلسلہ کو بند کر کے ایک مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً مشرک ہوتا ہے کیونکہ خدانمائی کا آئینہ اس کے انبیاء ہوتے ہیں اور اُنہیں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی حقیقی توحید دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہے.توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ خدا تعالیٰ کو ایک سمجھ لیا جائے بلکہ اُسے اپنی تمام صفات میں یکتا قرار دینا اور مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا توحید کا ایک اہم حصّہ ہے.جب کسی نبی کی بعثت پر ایک لمبا زمانہ گذر جاتا ہے تو توحید کا اقرار کرنے کے باوجود لوگ قسم قسم کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا حقیقی چہرہ لوگوں کی نگاہ سے مخفی ہو جاتا ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے مگر اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام مُردوں کو زندہ کیا کرتے تھے.پرندے پیدا کیا کرتے تھے.اور علم غیب سے حصّہ رکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ تمام عقائد مشرکانہ ہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جہاں اور غلط عقائد کی اصلاح فرمائی وہاں آپ نے ان مشرکانہ عقائدکی بھی پُر زور تردید فرمائی اور خدا تعالیٰ کی توحید دنیا میں قائم کی.پس انبیاء پر ایمان لائے بغیر توحید حقیقی کا قیام ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان لانے کے ساتھ ہی نبیوں پر ایمان لانا بھی ضروری قراردیا ہے.اگر یہ مقدس لوگ دنیا میں نہ آتے تو خدا تعالیٰ کا چہرہ لوگوں کو دکھائی نہ دیتا اور وہ ضلالت اور گمراہی سے نہ نکل سکتے.پس چونکہ خدا تعالیٰ کی شناخت انبیاء پر ایمان لانے کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے حنیف کے ساتھ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ کے الفاظ اس امر کی طرف توجہ دلانے کے لئے استعمال کئے گئے ہیں کہ ابراہیم ؑ مشرکوں میں سے نہ تھا بلکہ وہ سلسلہ نبوت کے دائمی اجراء کا قائل تھا.اسی لئے اس آیت کے معاً بعد یہ کہا گیا ہے کہ تم اس بات کا اقرار کرو کہ ہم تمام انبیاء سابقین پر بھی ایمان لاتے ہیں وَ مَاۤ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ اور جو کچھ اور نبیوں کو دیا گیا یا آئندہ دیا جائےگا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں.بے شک وَمَاکَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بیزار تھے اور ایک خدا کی پرستش کرتے تھے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مشرکین نے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بُت رکھے ہوئے تھے پھر بھی کسی بُت کی نسبت اُن کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی پرستش کیا کرتے تھے بلکہ وہ آپ کو کامل موحد تسلیم کرتے تھے.اور ان کی قدیم روایات اس کی تصدیق کرتی تھیں.اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان حالات میں بھی جو بائیبل میں موجود ہیں شرک کی تعلیم کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا.مگر یہ صرف اس ٹکڑہ کے ایک معنے ہیں جو اپنی جگہ درست ہیں لیکن حنیف کے ساتھ وَ مَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ کا اضافہ بتا رہا
Page 510
ہے کہ اس جگہ مشرک اس شخص کو نہیں کہا گیا جو عرف عام میں شرک کا ارتکاب کرتا ہے بلکہ اس شخص کو کہا گیا ہے جو سلسلۂ رسالت کو مسدود قرار دیتا ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی توحید کی اشاعت میںر وک بنتا ہے.اور اس کے مقابل پر اپنے ایک فرضی عقیدہ کو لا کر کھڑا کر دیتا ہے حالانکہ اصل مقام اطاعت کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو کچھ کہے انسان اُسے مان لے اور ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامبر آئے اس کی آواز پر لبیک کہے.قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ اِلٰۤى اِبْرٰهٖمَ تم کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم ؑ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِيَ اور اسماعیل ؑ اور اسحق ؑ اور یعقوب ؑ اور (اُس کی) اولاد پر اتارا گیا تھا اور جو کچھ موسیٰ ؑ اور عیسیٰ ؑکو دیا گیا تھا.(اسی مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَاۤ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ١ۚ لَا نُفَرِّقُ طرح)جو کچھ (باقی) انبیاء کو اُن کے ربّ کی طرف سے دیا گیا تھا.(اس تمام وحی پر ) ایمان رکھتے ہیں.ہم اُن میں بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ١ۖٞ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ۰۰۱۳۷ سےایک (نبی اور دوسرے نبی) کے درمیان(کوئی) بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں.حَل لُغَات.اَ لْاَسْبَاطِ: سِبْطٌ کی جمع ہے.اور سِبْطٌ کے معنے اصل میں پھیلائو کے ہوتے ہیں اسی وجہ سے لمبے بالوں کو سِبْطٌ کہتے ہیںسخی آدمی کو سِبْطُ الْکَفَّیْنِکہتے ہیں کیونکہ اس کا ہاتھ ہر ایک حاجت مند تک پہنچ جاتا ہے.بیٹے کے بیٹے کوبھی سِبْطٌ کہتے ہیں (مفردات)کیونکہ جب بیٹوں کے بیٹے ہو جائیں تو نسل کا پھیلائو شروع ہو جاتا ہے پس اَسْبَاط کے معنے پوتوں کے ہوں گے یا اُن کی نسل کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے پھیلانے کا باعث اور ذریعہ ہوئی.تفسیر.اس آیت سے ظاہر ہے کہ مسلم وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لائے اور نفس نبوت کے لحاظ سے اُن میںـ کوئی فرق نہ کرے.جن انبیاء کا اُسے علم ہو اُن کی نبوت کا نام لے کر اقرار کرے.اور جو معلوم
Page 511
نہیں اُن کی نبوت پر مجملاً ایمان لائے.یعنی یہ یقین کرے کہ ہر قوم میں خدا تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہے اور ہم سب کو سچا تسلیم کرتے ہیں.اور ان کی پیش کردہ تعلیموں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں.پس جو شخص اپنے زمانہ یا اس سے پہلے زمانہ کے سب نبیوں کی نبوت کا اقرار کرے اور کسی نبی کا انکار نہ کرے وہ مسلم ہے.کیونکہ تمام نبیوں کی نبوت کا اقرار کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فقرہ فرمایا ہے کہ نَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ.ہم اسکے فرمانبردار ہیں.جس سے معلوم ہوتا ہے.کہ اس اقرار کے بعد انسان مسلم بنتا ہے.اوریہ صرف اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ دنیا کے تمام انبیاء کی صداقت کا اقرار کرتا ہے.ہر مذہب کے پیرو اپنے اپنے مذہب کے نبیوں کی صداقت تو منواتے ہیں.لیکن دوسری اقوام کے انبیاء کی صداقت منوانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے.اسلام سب انبیاء کی صداقت کا اقرار کراتا ہے.خواہ وہ بنی اسرائیل میں آئے ہوں یا ہندوایران کے لوگوں میں مبعوث ہوئے ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک میں اصلاح کیلئے کھڑے کئے گئے ہوں مگر اس سے تفصیلی ایمان نہیں بلکہ صرف اجمالی ایمان مراد ہے.اگر تفصیلی ایمان مراد ہوتا تو وَ مَاۤ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ فرما کر اُن نبیوں کا ذکر نہ کیا جاتا جن کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں اور جن کے حالات کا قرآن کریم نے کہیں ذکر نہیں کیا.مگر پھر بھی اجمالی طور پر اُن پر ایمان لانا ضرور ی قرار دیا ہے.میں اس موقعہ پر مسلمانوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جو سب نبیوں کو مانے وہی مسلم ہے.اورآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیتے ہیںاور اس زمانہ میں مسیحیت موعودہ کا وعدہ بانی سلسلہ احمدیہ کے وجود میں پورا ہو چکا ہے.پس ہر شخص جو اسلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے اُس کا فرض ہے کہ وہ ہوشیار ہو جائے اور بے توجہی سے آپ کے دعویٰ کو نہ دیکھے.کیونکہ بے توجہی سے اسلام جیسی قیمتی چیز ہاتھ سے جانے کا اندیشہ ہے.مسلم وہی ہے جو خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں کو مانے اور مسیح موعود کی نبوت بھی اس سے مستثنیٰ نہیں.پس مسلمانوں کیلئے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے.لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ.اِس آیت کے یہ معنے نہیں کہ ہم انبیاء کے درجات میں فرق نہیں کرتے.کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَھُمْ عَلٰی بَعْضٍ (البقرۃ:۲۵۴)یعنی یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی تھی.پس اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب نبیوں کو درجہ اور مقام کے لحاظ سے ایک جیسا سمجھتے ہیں.بلکہ صرف یہ مطلب ہے کہ اُن پر ایمان لانے کے لحاظ سے ہم اُن میں کوئی فرق نہیں کرتے چاہے وہ شرعی نبی تھے یا غیر شرعی.ورنہ درجوں کا فرق تو خود قرآن کریم نے تسلیم کیا ہے.مسیحی مصنّف اِس آیت پر یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ حضرت اسما عیل علیہ السلام نبی نہ تھے مگر قرآن نے
Page 512
انہیں نبی کہہ دیا ہے.اوروہ دریافت کیا کرتے ہیں کہ اسما عیل ؑ کی نبوت کا کیا ثبوت ہے ؟ (تفسیر سیل زیر آیت ھذا) حالانکہ اگر وہ غور کریں تو یہی سوال اُلٹ کر اُن پر پڑتا ہے کہ اسحاق ؑ کی نبوت کا کیا ثبوت ہے جو ثبوت اسحاق ؑ کی نبوت کا ہے وہی اسمٰعیل ؑ کی نبوت کا ہے موسیٰ ؑ اپنے دادا اسحاق ؑ کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں.اورآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا اسماعیل ؑ کی نبوت کا اعلان کرتے ہیں.فرق یہ ہے کہ بائیبل نے بخل سے کام لے کر حضرت اسماعیل ؑ کی نبوت کا ذکر نہیں کیا.اور قرآن کریم جو کبھی کسی صداقت کا انکار نہیں کرتا.اُس نے نسلی تعصبات سے کام نہ لے کر دونوں بزرگوں کی بزرگی کا اقرار کیا ہے.آخر بنی اسرائیل کے پاس اسحاق ؑ کی نبوت کا اِس کے سوا کیا ثبوت ہے کہ ایک سچے نبی نے جس کی نبوت اُن کے خیال میں دلائل سے ثابت ہے.اسحاق علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا ہے.یہی دلیل ایک مسلمان دےگا کہ اسما عیل ؑ کی نبوت کا یہ ثبوت ہے کہ ایک سچے نبی نے جس کی نبوت دنیا کے تمام انبیاء کی صداقت کے دلائل سے زیادہ وزنی دلائل کے ساتھ ثابت ہے اُسے نبی قرار دیا ہے.اگر بائیبل کی شہادت سے اسحاق علیہ السلام نبی قرار پا سکتے ہیں.توقرآن کریم کی شہادت سے اسما عیل علیہ السلام کو کیوں نبی نہیں قرار دیا جا سکتا.اصل بات یہ ہے کہ مسیحی مصنّفوں کو حضرت اسما عیل علیہ السلام کی نبوت کے ماننے میں سوائے اس کے کوئی عذر نہیں کہ اُن کا ذکر بائیبل میں نہیں.حالانکہ بائیبل سے ثابت ہے کہ اُن کو سارہ کے حسد کی وجہ سے وطن چھوڑ کر بے وطنی کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی.اور جبکہ سار ہ کو اسما عیل ؑ سے اِس قدر دشمنی تھی کہ اُن کو گھر چھوڑنا پڑا اور وہ بہت دور ایک ملک میں چلے گئے.(پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۰) تو بنی اسرائیل نے اپنی کتب میں انکی کب تعریف کرنی تھی اور اُن کی نبوت کا کس طرح ذکر کرنا تھا.پس اُن کے حالات کا بائیبل میں نہ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں.پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گو کسی چیز کا عدم ذکر اس کے عدم وجود پر دلالت نہیں کرتا.مگر موجودہ بائیبل بھی ایسے اشارات رکھتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام سے بھی خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے تھے.اوّل تو اُن کا نام ہی دلالت کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیارے ہونے والے تھے.کیونکہ آپ کا الہامی نام اسمٰعیل تھا.جس کے معنے ہیں خدا نے سنی.اوریہ نام بلاوجہ نہیں ہو سکتا.چنانچہ پیدائش باب ۱۶آیت ۱۱ میں لکھا ہے.’’خدا وند کے فرشتے نے اُسے (یعنی حضرت ہاجرہ ؑ کو )کہا.کہ تو حاملہ ہے.اور بیٹا جنے گی.اس کا نام اسمٰعیل رکھنا کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا.‘‘ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسما عیل علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی بشارت کے ماتحت ہوئی تھی.اور الہامی طور پر آپ کا نام اسما عیل رکھا گیا تھا اور جو بچہ اللہ تعالیٰ کی بشارت کے ماتحت پیدا ہوا ہواور الہام میں اس کا
Page 513
نام بھی تجویز ہوا ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ نہیں تھا خود الہامِ الٰہی کی تکذیب کرنا ہے.پھرپیدائش باب ۱۷ آیت ۱۸ میں لکھا ہے.’’ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسمٰعیل تیرے حضور جیتا رہے.‘‘ اصل عبرانی الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ’’تیری آنکھوں تلے رہے اور تیرا مقبول ہو.‘‘ اِس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :.’’اور اسمٰعیل کے حق میں میں نے تیری سُنی دیکھ میں اسے برکت دو نگا.اور اُسے بر ومند کروںگا.اور اُسے بہت بڑھاؤںگا.اور اُس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے.اور میںاُسے بڑی قوم بناؤنگا.‘‘ (آیت ۲۰) اِن دونوں آیات کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اسمٰعیل ؑ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ ہو.کیونکہ ان کے الفاظ ہیں.’’تیرے حضور جیتا رہے ‘‘اور تیرے حضور جیتا رہنے کے معنے مقبول ہونے کے سوا اور کوئی نہیں ہوسکتے.اگر آپ کا یہ مطلب نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اس قدر کہہ دینا کافی تھا کہ وہ جیتا رہے.کیونکہ جس قدر لوگ زندہ رہے ہیں سب خدا تعالیٰ کے حضور ہی زندہ رہتے ہیں.اُس سے غائب نہیں ہوتے.پس ’’تیرے حضور‘‘ کے الفاظ بڑھانے کا اِس کے سواا ور کوئی مطلب نہیں تھا کہ تیرے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں سے ہو.اور نیک پاک اور خدا رسیدہ ہو چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں نے تیری سن لی.فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا١ۚ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا پس اگر وہ لوگ (اسی طرح) ایمان لے آئیں جس طرح تم اس (تعلیم) پر ایمان لائے ہو تو (بس ) وہ ہدایت پا گئے.هُمْ فِيْ شِقَاقٍ١ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ١ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُؕ۰۰۱۳۸ اور اگر وہ پھر جائیں تو (سمجھو کہ) وہ صرف اختلاف (کرنے) پر (تُلے ہوئے) ہیں.اس صورت میں اللہ (تعالیٰ) تجھے ضرور اُن (کے شر) سے بچائے گا.وہ بہت ہی سننے والا (اور) بہت ہی جاننے والا ہے.حَلّ لُغَات.شِقَاقٌ: شِقٌّ جانب کو کہتے ہیں.پس شِقَاقٌ کے معنی دوری کے ہیں.
Page 514
سَمِیْعٌ : کے معنے ہیں.بہت سننے والااور عَلِیمٌ:کے معنے ہیں.بہت جاننے والا.تفسیر.اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تشریح بیان فرمائی تھی کہ ایمان کامل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کوئی شرط نہ لگائے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم آجائے اسے مان لے.نہ قوم کی شرط ہونہ زمانہ کی.نہ ملک کی اور نہ یہ شرط ہو کہ پہلے نبیوں کو مانیں گے اور جو آئندہ آئیں گے.اُن کو نہیں مانیں گے.فرمایا.تم عالم ہو یا نہ ہو.اگر تمہیں پتہ لگے کہ فلاں شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو تم اسے فوراً مان لو.پس یہ کہنا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے نجات ملتی ہے.یہ سب ڈھکونسلے ہیں.ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ بغیر کسی شرط کے انسان ایمان لائے اور اس کے ساتھ کوئی قید نہ لگائے اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہنے کے لئے تیار رہے.اس جگہ باء اور مثل دونوں لفظ ہم معنے آئے ہیں اور بظاہر یہ ایک تکرار نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً تکرار نہیں.اصل بات یہ ہے کہ یہاں باء زائدہ ہے.مگر زائدہ کے یہ معنے نہیں کہ اس کے کوئی معنے ہی نہیں.بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئے معنے دیتی اورتاکید پیدا کرتی ہے.بعض لوگ زائدہ کا لفظ سنکر کہنے لگ جاتے ہیں.کہ کیا قرآن میں بھی زوائد ہیں.حالانکہ یہ عربی زبان کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بے حقیقت ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لئے استعمال ہوئی ہے جیسے اردو میں ’’ہی‘‘ کا لفظ ہے.یہ کوئی نئے معنے نہیں دیتا بلکہ پہلے معنوں کی تاکید کردیتا ہے.جیسے کہتے ہیں.’’یہ زید ہی ہے ‘‘.اس فقرہ میں جو ’’ہی ‘‘ استعمال ہوا ہے یہ معنوں کو مضبوط کرنے کیلئے استعمال ہوا ہے نہ کہ کوئی زائد معنے پیدا کرنے کیلئے.اِسی طرح باء ہے یہ مثل کی تاکید کیلئے آئی ہے.اور اس کے معنے ہیں.’’بالکل ویسے ہی ‘‘ اگر صرف مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا تو تھوڑی بہت اِدھر اُدھر ہونے کی گنجائش رہ جاتی تھی اور شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید پوری مشابہت مراد نہ ہو.لیکن باء کی موجودگی نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور پوری طرح واضح کر دیا کہ جب تک ایمان کا ہر ایک نقطہ دوسرے نقطہ کے مشابہ نہ ہو اُسوقت تک وہ ایمان ہی نہیں کہلاسکتا.زائدہ ہونے کے علاوہ باء استعانت کیلئے بھی ہو سکتی ہے.اور مراد یہ ہے کہ فَاِنْ دَخَلُوْا فِی الْاِیْمَانِ بِشَھَادَۃٍ مِثْلَ شَھَادَتِکُمْ.یعنی اگر وہ صداقت انبیا ء کی شہادت دیتے ہوئے اُن پر ایمان لے آئیں جیسے تم نے انبیاء کی صداقت کی شہادت دی ہے اور ان پر ایمان لے آئے تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے یعنی جب تک اُن کے ایمان کی وہی کیفیت نہ ہو جو تمہاری کیفیت ہے اُسوقت تک وہ ہدایت یافتہ نہیں سمجھے جاسکتے.یہ بھی تاکید کا ہی ایک
Page 516
غور کرو کیا صحابہؓکی بیویاں نہ تھیں.کیا اُن کے بچّے نہ تھے کیا اُن کی جائدادیں اور تجارتیں نہ تھیں.اگر وہ خدا کےلئے اپنی جانیں قربان نہ کرتے تو ہم تک اسلام کس طرح پہنچتا.ہم تو جہالتوں میں مبتلا ہوتے.کوئی بتوں کو ُپوج رہا ہوتا.اور کوئی کسی دیوی دیوتا کے آگے اپنا سر جھکا ئے ہوتا.خدا تعالیٰ کی ان پر ہزاروں ہزار برکات ہوں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو ہمارے لئے آگ میں ڈالا.اپنی اولادوں کو یتیم کیا.اپنی بیویوں کو بیوہ کیا.اپنے ماں باپ کو بے نوروبے چراغ کیا.اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا.مگر افسوس کہ اُن کی اس قدر عظیم الشان قربانی کے بعد اور اُن سے نورِ ایمان حاصل کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ مسلمان انہی کی طرح اس میدان میں نکلتے اور کہتے کہ ہم بھی وہی کچھ قبول کرتے ہیں جو صحابہ ؓ نے کیا.انہوں نے دنیوی تکالیف اور مصائب سے ڈر کر اپنے قدم پیچھے ہٹالئے اور اسلام جن قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے اُن میں حصّہ لینے سے انہوں نے ہچکچانا شروع کر دیا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ڈرتے کیوں ہو.اگر تم خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہو.تو وہی تمہاری حفاظت کرے گا.اور وہی تمہیں ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا.غرض اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو تم سمجھ لو کہ ان کے دلوں میں تمہاری نسبت سخت عداوت اور دشمنی ہے اور وہ تمہارے خلاف شرارتیں کریںگے مگر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کافی ہو گا وہ تمہیں ان کے حملہ سے خود بچائے گا.اور ان کی شرارتیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی.وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.فرماتا ہے یہ نہ سمجھ لو کہ اب خد اتعالیٰ کی طرف سے چونکہ وعدہ ہو گیا ہے.اس لئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ دعائیں کرو کہ ایسا ہی ہو.خدا تعالیٰ سننے والا ہے اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں اُن کا اُسے خود علم ہے.وہ آپ اُن کا انتظام کر دے گا.انسان کی دو۲ حالتیں ہوا کرتی ہیں.ایک یہ کہ انسان پر اس کا دشمن حملہ کرتا ہے اور اس حملے کا اُسے علم ہوتا ہے اور جہاں تک اُس کےلئے ممکن ہوتا ہے وہ اُس کا مقابلہ کرتا ہے.اور اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے.دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دشمن ایسے وقت میں حملہ کرتا ہے جبکہ اُسے خبر نہیں ہوتی.یا ایسے ذرائع سے حملہ کرتا ہے جن کی اُسے خبر نہیں ہوتی.مثلاً اس کے کسی دوست کو خرید لیتا ہے اور اس کے ذریعے اُسے نقصان پہنچادیتا ہے.یا رات کو اس پر سوتے سوتے حملہ کر دیتا ہے.یا راستہ میں چھپ کر بیٹھ جاتا اور اندھیرے میں حملہ کر دیتا ہے یا وہ اُسے تیر مار دیتا ہے یا کھانے میں زہر ملا کر اُسے کھلا دیتا ہے یا اس کا مال یا جانور چُرا لیتا ہے.یہ وہ حملے ہیں جو اُس کے علم میںنہیں ہوتے اور اس وقت ہوتے ہیں.جبکہ وہ بے خبر ہوتا ہے.اِن دونوں حملوں کے بچائو کی مختلف تدبیریں ہوتی ہیں.اللہ تعالیٰ
Page 517
فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ دشمن کس طرح اور کس رنگ میں حملہ کریگا.اگر تم کو اس کے حملہ کا علم ہو مگر تم دفاع کی طاقت نہ پاؤتو ایک سمیع اور علیم خدا موجود ہے.وہ جانتا ہے کہ دشمن تم پر حملہ آور ہے اور تم میں اس کے دفاع کی طاقت نہیں.پس تم گھبرائو نہیں.تم ہمیں آواز دو.ہم فوراً تمہاری مدد کیلئے آجائیں گے.اور اگرتم سوئے ہوئے ہو یا راستہ پر سے گذر رہے ہو یا تاریکی میں سفر کر رہے ہو اور دشمن نے اچانک تم پر حملہ کر دیا ہے یا کھانے میں زہر ملا دیا ہے یا چوری سے مال نکال لیا ہے.یا کسی دوست سے مل کر اُس نے تم پرحملہ کر دیا ہے اور تمہیں اس کا علم نہیں ہوا.توفرماتا ہے کہ ہم علیم ہیں ہم خوب جاننے والے ہیں اور ہمیں ہر قسم کی قوتیں حاصل ہیں.اس لئے ایسی حالت میں بھی تم گھبراؤنہیں.بلکہ اللہ تعالیٰ کو پکارواور اُس سے دعائیں کرو.وہ تمہاری تمام مشکلات کو دُور کر دیگااور تمہارے دشمن کو ناکام اور ذلیل کرےگا.صِبْغَةَ اللّٰهِ١ۚ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً١ٞ وَّ نَحْنُ (اے مسلمانو! ان سے کہو کہ ہم تو)اللہ کا دین (اختیار کریں گے) اور دین (سکھانے کے معاملہ) میں اللہ (تعالیٰ)سے کون بہتر ہوسکتا ہے.لَهٗ عٰبِدُوْنَ۰۰۱۳۹ اور ہم اُسی کی عبادت کرنے والے ہیں.حَلّ لُغَات.صِبْغَۃً کے معنے ہیں مِلَّت.دِین.فطرت.چمڑے کو رنگ دینا.غوطہ دینا، چمٹا دینا.(اقرب)اس لحاظ سے صِبْغَۃَ اللّٰہِ کے معنے ہیں اللہ کے دین کو اختیار کرو.یا اللہ کے بتائے ہوئے طریق کو اختیار کرو.یا اللہ کی دی ہوئی فطرت کو اختیار کرو.تفسیر.صِبْغَۃَ اللّٰہِ کے معنے جیساکہ حل لغات میں بتایا گیا ہے دین کے بھی ہیں.ملّت کے بھی ہیں.فطرت کے بھی ہیں اور کسی چیز کو رنگ دینے کے بھی ہیں یہ لفظ اس جگہ مفعول بہٖ استعمال ہوا ہے جو اس لفظ کے آخر کی زبر سے جو مفعول بہٖ کا نشان ہے ظاہر ہے عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جہاں کسی کو کسی کام کی ترغیب دلانی ہو وہاں اس فعل کو جس میں ترغیب کے معنے پائے جاتے ہیں حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف مفعول بہٖ بیان کر دیا جاتا ہے.یہاں بھی اِتَّبِعُوْا محذوف ہے اور اصل فقرہ یوں ہے اِتَّبِعُوْا صِبْغَۃَ اللّٰہِ یعنی تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرو اور اس سوال کو جانے دو کہ خدا تعالیٰ نے یہ تعلیم کس شخص پر اتاری ہے اور وہ کونسی قوم
Page 518
سے تعلق رکھتاہے بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے اور خدا ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی اس لئے اس کی طرف سے جو دین بھی آئے اس کے ماننے میں تمہیں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے.کیونکہ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کی اتباع کرے.ملّت کے مفہوم کو مدّنظر رکھتے ہوئے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی نیکی اُسی وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس کا نفس اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کے ماتحت چلتا ہے لیکن جب وہ خدائی راہنمائی کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور خدائی طریق کے علاوہ کوئی اور طریق اختیار کر لیتا ہے تو وہ خواہشات اُسے ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گرادیتی ہیں.پھر فطرت کے مفہوم کے لحاظ سے اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ فطرتِ صحیحہ سے کام لیتے ہوئے اختلافات کا فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے پاک بنائی ہے اور اس سے سچائی کو پہچاننے میں بڑی بھاری مدد ملتی ہے.مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ فطرتِ صحیحہ مذہب کی قائم مقام ہے وہ مذہب کی قائم مقام نہیں بلکہ مذہب کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے اگر کسی کو فطرتِ صحیحہ نصیب نہ ہو تو اُسے سچا مذہب بھی معلوم نہیں ہو سکتا.فطرت صحیحہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کے پاس اس کے دوست کا خط آجائے تو وہ اُس کے پڑھنے کے لئے عینک لگالے لیکن اگر وہ عینک لگا کر ہی بیٹھا رہے اور خط نہ پڑھے تو ہر شخص اُسے احمق قرار دیگا.اسی طرح دین بھی ایک خط ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا اور عینک فطرت صحیحہ ہے.جس طرح خط اصل چیز ہے اور اس سے منہ پھیرنا اور صرف عینک پر اکتفاء کر لینا جہالت ہے.اسی طرح جو شخص فطرت صحیحہ کے بعد مذہب کی ضرورت نہیں سمجھتا وہ بھی احمق ہے.صِبْغَۃَ اللّٰہِ کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو.یعنی ہمیشہ صفاتِ الہٰیہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو.اور دیکھتے رہو کہ کیا تم صفات الٰہیہ کے مظہر بنے ہو یا نہیں بنے.حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی غرض کے لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صفاتِ الہٰیہ کا مظہر بنے اور اس کی قابلیت خود اس نے انسانی فطرت کے اندر و دیعت کر دی ہے.کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی ربوبیت کا مظہر نہیں بن سکتایا رحمانیت کا مظہر نہیں بن سکتایا رحیمیت کا مظہر نہیں بن سکتا.یا مَالِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ کا مظہر نہیں بن سکتا.اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ تمام قابلیتیںرکھ دی ہیں اور اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے کہ خَلَقَ اللّٰہُ اٰدَمَ عَلیٰ صُوْرَتِہٖ (بخاری کتاب الاستئذان باب بدء السلام) یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا.
Page 519
یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مادی شکل نہیں اور نہ اسلام اس کا قائل ہے پس اللہ تعالیٰ کی صورت پر آدم کوپیدا کرنے کا یہی مفہوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم میں صفاتِ الہیہ کا مظہر بننے کی قابلیت رکھ دی.اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان صفات کو اپنے وجود کے ذریعہ ظاہر نہیں کر سکتا.جس طرح خدا تعالیٰ ستّار ہے.اسی طرح وہ بھی ستّار بن سکتا ہے.جس طرح خدا شکور ہے اسی طرح وہ بھی شکور بن سکتا ہے.جس طرح خدا وہاب ہے اسی طرح وہ بھی وہاب بن سکتا ہے.جس طرح خدا رزّاق ہے اسی طرح وہ بھی اپنے دائرہ میں رزاق بن سکتا ہے.اور درحقیقت اسلامی نقطہ نگاہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی وہی شخص حاصل کرتا ہے جو صفاتِ الٰہیہ کا مظہربن کر اللہ تعالیٰ سے مشارکت پیدا کر لیتا ہے.اور اسی کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے.دیکھو آک کا ٹِڈا آک کے پتوں میں رہ کر ویسا ہی رنگ اختیار کر لیتا ہے اور تیتری جن پھولوں میں اُڑتی پھرتی ہے اُن کا رنگ اختیار کر لیتی ہے.کیا ہم ٹِڈّوں اور تیتریوں سے بھی گئے گذرے ہیں.اور ہمارا خدا نعوذباللہ آک اور پھولوں سے بھی گیا گذرا ہے کہ ٹڈا اگرآک میں رہتا ہے تو ان کا رنگ قبول کر لیتا ہے تیتریاںجن پھولوں میں رہتی ہیں ان کا رنگ اخذ کر لیتی ہیں.لیکن خدا تعالیٰ کے بندے اس کے پاس جائیں اور وہ اس کا رنگ قبول نہ کریں.دراصل اپنے دل کی بدظنی ہی ہوتی ہے جو انسان کو ناکام و نامراد رکھتی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں.خدا تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے.اَ نَاعِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ.(صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا والتوبۃ والاستغفار باب الحث علی ذکر اللہ ) جیسا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس سے سلوک کرتا ہوں.وہ لوگ جن کے دلوںمیں اپنی عظمت کا احساس نہیں ہوتا یا خد ا تعالیٰ کے متعلق یقین نہیں ہوتا ان کو کچھ نہیں ملتا.لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں معزز بنایا ہے اور بڑی بڑی طاقتیں عطا کی ہیں اور وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے اور بڑے بڑے انعام دینے والا ہے وہ خالی نہیں رہتے بلکہ اپنے ظرف کے مطابق اپنا حصہ لے کر رہتے ہیں.پس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں توجہ دلائی ہے کہ تم دنیا میں کسی نہ کسی کا رنگ اختیار کئے بغیر نہیں رہ سکتے.اور جب تم نے بہرحال کسی کا رنگ اختیار کرنا ہے تو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنے دوستوں کا رنگ اختیار نہ کرو.تم اپنے بیوی بچوں کا رنگ اختیار نہ کرو تم اپنے اساتذہ کا رنگ اختیار نہ کرو تم اپنے ماحول کا رنگ اختیار نہ کرو.تم اپنی حکومت کا رنگ اختیار نہ کرو بلکہ تم خدائے واحد کا رنگ اختیار کرو.کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے اور اس سے تعلق ہی تمہاری نجات کا موجب ہو سکتا ہے.وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰہِ صِبْغَۃً اور اللہ تعالیٰ سے بہتر اور خوبصورت رنگ تم پر اور کون چڑھا سکتا ہے.اس رنگ کے بعد تم بہروپئے نہیں بنوگے بلکہ ایک حسین ترین وجود بن جائو گے جسے دیکھ کر دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو جائیںگی اور
Page 521
برطانوی نمائندہ نے امریکہ سے بذریعہ تار بھجوائے اور انگلستان کو۲۸ سو ہوائی جہاز پہنچ گئے.وہ کہنے لگے اس کرّہ سے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جا سکتی.میں نے کہا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کُرّے کا اور اسی طرح اور ہزاروں لاکھوں کُرّوں کا خدا کوئی اور ہے کیونکہ میں اپنے ذاتی تجربہ سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام انسان پر نازل ہوتا ہے جو کئی قسم کی غیب کی خبروں پر مشتمل ہوتا ہے پس آپ بے شک اس مرکز کو ہی خدا مان لیں.لیکن ہم تو ایک علیم اور خبیر ہستی کو خدا کہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر قدرت بھی ہوتی ہے اس کے اندر جلال بھی ہوتا ہے.اس کے اندر جمال بھی ہوتا ہے.اس کے اندر علم بھی ہوتا ہے.اس کے اندر حکمت بھی ہوتی ہے.اس کے اندر بسط کی صفت بھی ہوتی ہے.اس کے اندر مُحی ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے.اس کے اندر مُمیت ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے.اس کے اندر حلیم ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے.اس کے اندر مُہیمن ہونے کی صفت بھی ہوتی ہے غرض بیسیوں قسم کی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں اسی طرح اس کا نور ہونا.اس کا وہاب ہونا.اس کا شکور ہونا.اس کا غفور ہونا.اس کا رحیم ہونا.اس کا ودود ہونا.اس کا کریم ہونا.اس کا ستار ہونا اور اسی طرح اور کئی صفات کا اس کے اندر پایا جانا ہم تسلیم کرتے ہیں جب ایک طرف یہ صفات اس مرکز میں نہیں پائی جاتیں اور دوسری طرف ہم پر ایک ایسی ہستی کی طرف سے الہام نازل ہوتا ہے جو اپنی صفات کو اپنے کلام کے ذریعہ دُنیا پر ظاہر کرتا ہے اور باوجود اس کے کہ ساری دنیا مخالفت کرتی ہے پھر بھی اس کا کلام پورا ہو جاتا ہے تو اس ذاتی مشاہدہ کے بعد ہم آپ کی تھیوری کو کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں.اس پروہ کہنے لگے کہ اگر یہ باتیں درست ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ تھیوری باطل ہے کیونکہ اس کلام کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایسا خدا نہیں جس کے تابع یہ تمام مرکز ہو.غرض صِبْغَۃَ اللّٰہِ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے اور اس کے رنگ میں رنگین ہونے کی نصیحت کی گئی ہے جو انسانی پیدائش کا حقیقی مقصد ہے اور جس پر بنی نوع انسان کی نجات اور اللہ تعالیٰ کا قرب منحصر ہے.قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَ هُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ١ۚ وَ لَنَاۤ تو (اُن سے) کہہ.کیا تم ہم سے اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا بھی ربّ ہے اور تمہارا بھی ربّ ہے اور ہمارے اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ١ۚ وَ نَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَۙ۰۰۱۴۰ اعمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لئے.اور ہم تو اس سے اخلاص (کا تعلق ) رکھتے ہیں.تفسیر.اس آیت میں کیا ہی لطیف دلیل دی ہے.فرماتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے ہدایت صرف
Page 522
ہماری قوم میں محدود کر دی ہے اس کو ہم کب مان سکتے ہیں اگر کسی اجنبی شے کے متعلق تم یہ بات کہتے تو تحقیق کی ضرورت بھی ہوتی مگر تم تو خدا کے متعلق یہ بات کہتے ہو جو ہمارا بھی ربّ ہے اور تمہارا بھی پھر ہم کس طرح اس بات کو مان لیں کہ بنو اسحاق سے باہر نبی نہیں آسکتا.اصل سوال تو یہ ہے کہ نبی بھیجا کون کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے تو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جسے کوئی فطرتِ صحیحہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی.وہ تمہارا بھی ربّ ہے اور ہمارا بھی.اگر وہ صرف تمہارا ہی ربّ ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ وہ ہمارے سوا کسی اور سے تعلق نہیں رکھ سکتا مگر جب وہ ہمارا بھی ربّ ہے اور تمہارا بھی تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تو دے دے اور ہمیں چھوڑ دے.لَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ اَعْمَالُكُمْ.فرماتا ہے کہ دین میں حسد کی بھی کوئی وجہ نہیں کیونکہ کوئی شخص دوسرے کی کمائی نہیں لے سکتا.ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جزا کا مستحق ہو گا.تمہارے اعمال تمہارے کام آئیںگے اور جس قوم میں سے یہ نبی آیا ہے اس کے افراد کے اعمال اس کے کام آئیں گے جو شخص جس قدر کوشش کرے گا اسی قدر انعام پائے گا.کوئی قومی رعایت نہیں ہو گی.وَ نَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ اور ہم تو اسی سے اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں اس میں بتایا کہ ہماری محبت ایسی نہیں کہ اگر وہ کچھ دے تو ہم اس پر ایمان لائیں.بلکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ خواہ وہ ہمیں کچھ دے یا نہ دے تب بھی ہم اسی کے لئے وقف ہیں اور اسی کے اطاعت گزار رہیں گے.اس کے سوا ہمیں کوئی اور چیز مطلوب نہیں.اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ (اے اہل کتاب!) کیا تم (یہ) کہتے ہو کہ ابراہیم ؑ اور اسمٰعیل ؑ اور اسحق ؑ اوریعقوبؑ وَ الْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى١ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اور (اس کی) اولاد یہودی یا مسیحی تھے؟ تو (ان سے ) کہہ کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو اَمِ اللّٰهُ١ؕ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ یا اللہ (تعالیٰ) ؟ اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس شہادت کو جو اُس کےپاس اللہ (تعالیٰ) کی
Page 523
اللّٰهِ١ؕ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۰۰۱۴۱تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ طرف سے ہو چھپائے.اور اللہ (تعالیٰ) اس سے ہرگز ناواقف نہیں ہے جو تم کرتے ہو.یہ وہ جماعت ہے جو(اپنا زمانہ خَلَتْ١ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ١ۚ لَا تُسْـَٔلُوْنَ پورا کر کے ) فوت ہو چکی ہے.اور جو کچھ اس نے کمایا (اُس کا نفع نقصان ) اُس کے لئے ہے اور جو کچھ تم نےکمایا عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَؒ۰۰۱۴۲ ( اُس کا نفع نقصان) تمہارے لئے ہے اور جو کچھ وہ کرتے تھے اُس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا.تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کا یہ دعویٰ بیان کرتا ہے کہ ابراہیم ؑ.اسماعیل ؑ.اسحٰق ؑ یعقوب ؑاور اس کی اولاد بھی یہودی یا مسیحی تھے.قرآن کریم اس کا ایک سادہ سا جواب دیتا ہے مگر وہ ایسا جواب ہے کہ جس سے اُن پر موت وارد ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم ؑ.اسماعیل ؑ.اسحاق ؑ.یعقوب ؑ اور ان کی اولاد سے تعلق رکھنے والے افراد توریت اور انجیل کے زمانہ سے بہت پہلے گذر چکے تھے اور توریت جسے وہ الہامی مانتے ہیں.اس میں اس کا صاف طور پر ذکر آتا ہے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دانستہ جھوٹ بولتے ہو اور ان گواہیوں کو چھپاتے ہو جو تورات میں موجود ہیں جب اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہےکہ یہ لوگ پہلے گذر چکے تھے تو ان کا ایمان اس چیز سے جو ان کے بعد آئی کس طرح وابستہ ہو سکتا ہے اور وہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام پر ایمان لانے والے کس طرح قرار دیئے جا سکتے ہیں.یہ ویسی ہی حماقت ہے جیسے پادری وُڈؔ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ ابراہیم بھی کفارہ پر ایمان لایا تھا تب اس کی نجات ہوئی.یا جیسے بعض شیعہ احباب کہہ دیا کرتے ہیں کہ اِنَّ مِنْ شِیْعَتِہٖ لَاِبْرٰھٖمَ(الصّافات: ۸۴) سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے.فرماتا ہے ہم تمہاری بات مانیں یا تمہاری کتاب کو سچا تسلیم کریں.تمہاری تورات تو کہتی ہے کہ ابراہیم ؑ زمانہ نزولِ تورات سے بہت پہلے ہوا اور تم اسے یہودی قرار دے رہے ہو.یہ کیسی احمقانہ بات ہے.تعجب ہے کہ اس زمانہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی قرار دینے والے لوگ موجود ہیں چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں JUDAISM کے نیچے لکھا ہے.(IBRAHIM IS CONSIDERED TO HAVE BEEN THE FIRST ADHERENT OF JUDAISM) ( vol 13 page 165 ۱۹۵۰انسائیکلوپیڈیا برٹینیکا
Page 524
یعنی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہودیت کے سب سے پہلے پیرو کار تھے.(اَلْعِیَاذُ بِاللہِ ) تِلْکَ اُمَّۃٌ قَدْخَلَتْ لَھَا مَا کَسَبَتْ وَلَکُمْ مَاکَسَبْتُمْ.فرماتا ہے یہ ایک اُمت تھی جو گذر چکی.تم کیوں اپنی غلطیوں میں ان کو شریک کرتے ہو.وہ اپنے اعمال کے آپ ذمہ دار ہیں اور تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو.پس اس بات سے کیا فائدہ کہ تم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہو.تم اپنے ایمان کی فکر کرو.اُن کا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیگا.اور نہ اُن کی نیکیاں تمہاری نجات کا موجب بن سکیں گی.گویا وہی مضمون جو آیت لَاتَزِرُ وَازِرَۃٌ وِّزْرَاُخْرٰی(الانعام:۱۶۵) میں بیان کیا گیا ہے.اس کو نئے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اپنے آبائو اجداد کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اپنے اعمال پر نگاہ ڈالیں اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا وہ نجات کے مستحق ہیں یا نہیں.اس رکوع کی پچھلی آیات میں اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہ بنو اسحاق کے انعاماتِ نبوت سے محروم ہو جانے کے بعد بنو اسماعیل ہی حقدار انعام تھے کیونکہ ان کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی.خصوصاً ایک صاحبِ شریعت نبی کی بعثت کی.آیت ۱۳۱و۱۳۲ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو سمجھایا کہ ملّتِ ابراہیمی کو ترک کر کے بیوقوف نہ ہو جانا.جو یہ ہے کہ جو حکم بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے اُسے قبول کر لیا جائے.جو شخص اس طریق کو اختیار نہیں کریگا وہ نقصان اُٹھائیگا.آیت۱۳۳ میں بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم ؑ نہ صرف خود اس طریق پر عامل تھے بلکہ ان کی اولاد بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کرتی چلی آئی ہے کہ ہمیشہ خدا کے فرمانبردار رہنا اور جب بھی کوئی مامور آئے اس کے حزب میں داخل ہو جانا.آیت ۱۳۴ و۱۳۵ میں بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو ان کی اولاد نے عہد بھی کیا تھا کہ وہ واحد خدا کی پرستش کرینگے اور اس کے کامل فرمانبردار رہیں گے اب تم لوگ اگر سچے اسرائیلی ہو تو تمہارا فرض ہے کہ اس عہد کو پورا کرو اور حضرت یعقوبؑ کی طرح فرمانبرداری کر کے دکھائو.صرف اُن کی اولاد سے ہونا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دہ ہے.آیت۱۳۶ میں فرمایا دیکھو یہ ِضد چھوڑ دو کہ یہودی یا مسیحی ہونے کے بغیر نجات نہیں.ابراہیمی طرزِ عمل اختیار کرو یعنی ہر حکم کو جس زمانہ میں بھی آئے مان لینا اور اس حکمِ الہٰی کے مقابل میں کسی روک کی پرواہ نہ کرنا.آیت ۱۳۷ میں مسلمانوں کو مخاطب کیا اور انہیں توجہ دلائی کہ وہ لوگ طریق ابراہیمی اختیار کریں یا نہ کریں مگر تم ہمیشہ اس بات کا اقرار کرو کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہم اُسے تسلیم کرتے ہیں.آیت۱۳۸ میں بتایا کہ اگر اہل کتاب تمہاری طرح اس عقیدہ پر راضی ہو جائیں تو سکھ پائیں گے ورنہ سزا.آیت۱۳۹ میں تاکید فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو رنگ بھی چڑھائے وہ اپنے اوپر چڑھالو.
Page 525
یعنی اسی رنگ میں رنگین ہو جائو جو اس کا مامور چاہے.آیت۱۴۰ میں فرمایا کہ ان اہل کتاب سے کہو کہ کیا تم خدا تعالیٰ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو کہ اس نے تمہیں کیوں اپنے کلام کے لئے چن لیا.یہ اُس کا فضل ہے.وہ ہمارے اور تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے پس جو اخلاص سے کام لے گا وہی انعام پائےگا.آیت۱۴۱ میں فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ اگر یہودی یا مسیحی قوم میں نجات ہے تو حضرت ابراہیم ؑ اور ان کے بیٹے پوتوں کا کیا حال تھا کیا وہ بھی یہودی تھے ؟ یہ تو جھوٹ ہے کیونکہ وہ تمہاری مسلّمہ آسمانی کتاب سے پہلے زمانہ میں ہوئے ہیں.آیت۱۴۲ میں اس قدر اتمامِ حجت کے بعد فرمایا کہ یہ نبیوں کا گروہ اپنے زمانہ میں گذر گیا.ان نبیوں کے اعمال تمہارے کام نہیں آسکتے.نہ مسیح ؑ کا تکلیف اُٹھانا تمہاری نجات کا موجب بن سکتا ہے.تم سے تمہارے اعمال کی نسبت پوچھا جائے گا.اس لئے تمہیں اپنا فکر کرنا چاہیے.سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ کم عقل لوگ ضرور کہیں گے کہ ان (مسلمانوں) کو اِن کے اس قبلہ سے جس پر یہ (پہلے) تھے الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا١ؕ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ١ؕ يَهْدِيْ کس چیز نے پھرا دیا ہے.(جب وہ ایسا کہیں) تُو (اُن سے) کہنا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں.مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۰۰۱۴۲ وہ جسے چاہتا ہے ایک سیدھی راہ دکھا دیتا ہے.حَلّ لُغَات.سُفَھَآءُ: سَفِیْہٌ کی جمع ہے.اور اَلسَّفْہُ کے معنے ہیں خِفَّۃُ الْحِلْمِ حلم کی کمی.اَلْجَھْلُ جہالت.اَلْخِفَّۃُ ہلکا پُھلکا ہونا.اَلْـحَرَکَۃُ حرکت.اَ لْاِضْطِرَابُ اضطراب(اقرب) پس سَفِیْہ کے معنے ہوئے کم علم.کم عقل.بات کو سمجھے بغیر بول اُٹھنے والے.سطحی نگاہ والے.بے استقلال.اَلْقِبْلَۃُ: اَلْجِھَۃُ.کُلُّ مَا یُسْتَقْبَلُ مِنْ شَیْ ءٍ قبلہ کے معنے ہیں جہت.ہر وہ چیز جس کی طرف منہ کیا جائے.(اقرب) عَلَیْھَا.یہاں عَلٰی کے معنے جسمانی قیام کے نہیں بلکہ عمل اور عقیدہ کے لحاظ سے کھڑا ہونا مراد ہے.ہمارے
Page 526
ہاں بھی کہتے ہیں کہ ’’جس پر تم قائم ہو‘‘ مطلب یہ کہ جس عقیدہ کے تم پابندہو.پس کَانُوْا عَلَیْھَا کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وہ پابند تھے.تفسیر.قرآن کریم کا طریق ہے کہ جب وہ کوئی اہم بات بیان کرنا چاہتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ فوری طور پر اس کے متعلق اپنا حکم بیان کر دے تمہید کے طور پر بعض باتوں کا ذکر کر دیتا ہے تاکہ اس چیز کی اہمیت لوگوں پر واضح ہو جائے اور ان کے قلوب پہلے سے ہی الہٰی حکم کو بشاشت کے ساتھ تسلیم کرنے اور اس کے مطابق اپنے اندر تغیر پیدا کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اور اُن پر کم سے کم ابتلاء آئے.کیونکہ قرآن کریم کی غرض لوگوں کو ہدایت دینا اور انہیں شریعت کے ساتھ ساتھ حکمت سکھانا بھی ہے.پس وہ چاہتا ہے کہ جہاں تک لوگوں کو ٹھوکر کھانے سے بچایا جا سکے انہیں بچا نے کی کوشش کی جائے جیسے روزوں کا حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں اور قومیں بھی روزے رکھتی چلی آئی ہیں اور یہ روزے اس لئے مقرر کئے جاتے رہے ہیں تاکہ تقویٰ پیدا ہو.اس تمہید کے بعد فرمایا کہ تم پر بھی روزے فرض کئے جاتے ہیں.اسی طرح یہاں بھی تحویل قبلہ کا حکم دینے سے پہلے لوگوں کی طبائع کو اس کے لئے تیار کیا اور آنیوالے انقلاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا.سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا.یعنی ایسے لوگ جو حکمت سمجھے بغیر اعتراض کر دینے کے عادی ہیں عنقریب ایک اعتراض کرنے والے ہیں اور وہ اعتراض باوجود نہایت لغو ہونے کے دشمن کرتے ہی چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلہ سے جس پر وہ پہلے قائم تھے کس چیز نے دوسری طرف پھرا دیا ہے.حالانکہ اس وقت تک اس بارہ میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو.مگر اصل حکم کے نازل کرنے سے پہلے ہی دشمن کا اعتراض بیان کر دیا اور بتا دیا کہ ہم عنقریب تحویل قبلہ کے بارہ میں ایک حکم دینے والے ہیں جس پر بعض لوگ جو کم علم اور کم عقل ہیں یا بات کو سمجھے بغیر بول اٹھنے والے ہیں یہ اعتراض کرینگے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے جس پر وہ پہلے قائم تھے کس نے پھرا دیا.مگر تم نے اس اعتراض سے گھبرانا نہیں کیونکہ اب اللہ تعالیٰ قبلہ کے بارہ میں ایک نیا حکم نازل فرما کر تمہارے ایمانوں کی آزمائش کرنے والا ہے.سَیَقُوْلُ میں س تاکید اور استمرار کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور استمرار میں مستقبل کا زمانہ شامل ہوتا ہے.اسی رنگ میں سَوْفَ کا لفظ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور وہ بھی تاکید کے لئے آتا ہے لیکن سَوْفَ کی نسبت س کا زمانہ زیادہ قریب ہوتا ہے.بہر حال سَیَقُوْلُ کے الفاظ میں یہ خبر دی گئی کہ عنقریب بعض کم عقل لوگ ایک اعتراض کرنیوالے ہیں اور وہ اعتراض باوجود نہایت لغو ہونے کے دشمن کرتا ہی چلا جائے گا.چنانچہ ہم دیکھتے
Page 528
بلکہ اس کی تعیین بعض اور حکمتوں پر مبنی ہوتی ہے مثلاً بڑی وجہ تو یہی ہے کہ اس کے ذریعے اتحاد قائم رہتا ہے.اگر نماز کے لئے کوئی خاص جہت مقرر نہ کی جائے تو کسی کا منہ مشرق کو ہو گا اور کسی کا مغرب کو کسی کا شمال کو اور کسی کا جنوب کو اور ان میں کوئی تنظیم اور یکجہتی نظر نہیں آئیگی.پس مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے اور پھر صفوں کو درست رکھنے کے لئے اسلام نے ایک جہت مقرر کر دی.ہاں ریل اور جہاز میں اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو انسان جدھر چاہے نماز پڑھ سکتا ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ جہت بالذات مقصود نہیں بلکہ تنظیم اور اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کے لئے اس کی تعیین کی گئی ہے.پھر بیت اللہ کو قبلہ عالم مقرر کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ مکہ والوں میں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے جو دنیا کی ہدایت اور راہنمائی کا موجب ہو.اس کے ہاتھ پر آیاتِ الہٰیہ کا ظہور ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک کامل شریعت عطا ہو.وہ شریعت کے اسرار اور غوامض کو بیان کرنےوالا ہو اور تزکیہ نفوس اس کا کام ہو.یہ دعا اس امر کا تقاضا کرتی تھی کہ آنے والا عظیم الشان نبی اور اس کے متّبع بیت اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں تاکہ جب بھی وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں انہیں وہ ابراہیمی دعا یاد آجائے جو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے کی تھی.جب ایک انسان اَللّٰہُ اَکْبَرْکہہ کر نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور بیت اللہ کی طرف اس کا منہ ہوتا ہے تو معاً اس کا ذہن اس دعا کی طرف پھر جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں میرا کام بھی یہی ہے کہ میں لوگوں کو آیاتِ الہٰیہ کی طرف توجہ دلائوں.اُنہیں کتاب اللہ کا علم سکھائوں.احکامِ الہٰیہ کی حکمت اُن پر روشن کروں اور انہیں پاکیزہ اور مطہّر بنانے کی کوشش کروں.یہ عظیم الشان مقصد لنڈن یا نیویارک کی طرف منہ کرنے سے کسی کی آنکھوں کے سامنے نہیں آسکتا.نہ پیرس کی طرف منہ کرنے سے انسانی قلب میں یہ ولولہ پیدا ہو سکتا ہے.اس کی طرف منہ کرنے سے تو ناچنے اور گانے کا ہی خیال آئے گا عبادت اور زہد اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا کبھی خیال نہیں آئے گا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ہر جگہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرب میں ہے اور امریکہ میں نہیں یا مکہ میں ہے اور افریقہ میں نہیں.لیکن بعض چیزیں اپنے اندر ایسے محرکات رکھتی ہیں جو انسان کو غیر معمولی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں اس لئے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا گیا ہے ورنہ خدا تعالیٰ ہر قسم کے تجسّم سے بالا ہے اور اس کے قرب کے دروازے دنیا کے ہر انسان کے لئے کھلے ہیں.لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ.پر بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہی الفاظ سورۂ بقرہ کے چودھویں رکوع میں
Page 529
استعمال ہوئے تھے تو وہاں اس کے یہ معنے کئے گئے تھے کہ تم جدھر چاہو منہ کرو.اب انہی الفاظ سے ایک قبلہ کی دلیل اخذ کی گئی ہے د۲و متضاد مضمون ایک ہی دلیل سے کس طرح نکل سکتے ہیں.اس کا جواب یہ ہے کہ نہ پہلے اس دلیل سے قبلہ کا ردّ کیا گیا ہے اور نہ اس سے قبلہ کو ثابت کیا گیا ہے بلکہ پہلی جگہ لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَیْنَمَا تَوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ(آیت ۱۱۶) میں بتایا تھا کہ سب کچھ خدا کا ہے وہ ایک دن تمہیں مشرق و مغرب کا حکمران بنا دیگا اور تمہیں اپنے فضل سے سب کچھ دے دیگا.اور اب یہ بتایا ہے کہ قبلہ اصل مقصود نہیں ہوتا کہ اس پر اعتراض کیا جائے بلکہ اصل چیز تو خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے اور خدا جدھر منہ کرنے کا حکم دے اسی طرف منہ کرنا انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا مستحق بناتا ہے.پھر پہلی آیت بھی مدینہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ دشمنوں کے نزدیک بھی وہاں قبلہ مقرر ہو چکا تھا.پھر قرآن کریم یہ کب کہہ سکتا تھا کہ کسی خاص قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں.یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب قبلہ مقصود نہیں تو پھر مقرر کیوں کیا.کیونکہ جس طرح کسی مشورہ کے لئے جمع ہونے والے لوگ گو کسی خاص جگہ پر جمع ہونا اپنا مقصد نہیں ٹھہراتے مگر پھر بھی اُنکو جگہ اور وقت کی تعیین کرنی پڑتی ہے اسی طرح قبلہ گو اصل مقصود نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنے اور اُن کی صفوں کو درست رکھنے کے لئے ایک جہت مقر ر کر دی ہاں سفر میں اگر قبلہ معلوم نہ ہو یا قبلہ تو معلوم ہو مگر نماز شروع کرنے کے بعد ریل یا جہاز یا سواری کا رُخ قبلہ کی طرف سے بدل جائے تو نماز میںکوئی نقص واقع نہیں ہوتا جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہت بالذات مقصود نہیں بلکہ اتحاد اور تنظیم اور صفوں کی درستی کے لئے اُس کی تعیین کی گئی ہے.پھر فرمایا يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایک سیدھی راہ دکھا دیتا ہے.’’ایک سیدھی راہ ‘‘ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہر زمانہ کے لحاظ سے تعلیمات کسی قدر فرق کے ساتھ آتی ہیں کیونکہ یہ الہٰی سنت ہے کہ وہ جس قوم پر فضل کرتا ہے اس کے مناسب حال تعلیم بھی بھیج دیتا ہے مسلمانوں کے مناسب حال قبلہ کعبہ ہی تھا چنانچہ آخر اس نے ان کو اس کی طرف پھیر دیا اوروہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع کر دیا تھا اور جو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی آواز کے پیچھے چلیں اور مشرق و مغرب کی حد بندیوں سے اپنی نگاہ کو بالا رکھیں.اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی مخلصانہ اطاعت کی توفیق بخشی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پھیرتے ہی انہوںنے بیت اللہ کی طرف اپنے منہ کر لئے اور صراطِ مستقیم پر دوڑتے چلے گئے.
Page 530
وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى اور (اے مسلمانو! جس طرح ہم نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے) اُسی طرح ہم نے تمہیں ایک اعلیٰ درجہ کی اُمت بنایا ہے تاکہ تم النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا١ؕ وَ مَا جَعَلْنَا (دوسرے) لوگوں کے نگران بنو اور یہ رسول تم پر نگران ہو.اور ہم نے اس قبلہ کو الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ جس پر تُو (اس سے پہلے قائم) تھا صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ تا ہم اُس شخص کو جواس رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ١ؕ وَ اِنْ كَانَتْ اُس شخص کے مقابل پر جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے (ایک ممتاز حیثیت میں) جان لیں اور یہ امر ان لوگوں کے سوا لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ١ؕ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے (دوسروں کے لئے) ضرور مشکل ہے.اور اللہ (تعالیٰ ایسا ) نہیں کہ تمہارے لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۰۰۱۴۴ ایمانوں کو ضائع کرے.اللہ یقیناً سب انسانوں پر نہایت مہربان (اور) باربار رحم کرنے والا ہے.حَلّ لُغَات.اُمَّۃً وَسَطًا.وَسَط کے معنے درمیان کے ہوتے ہیں چونکہ درمیان میں رہنے والی (یعنی حدِّ اعتدال کے اندر رہنے والی) چیز ہمیشہ اعلیٰ ہوتی ہے.اس لئے محاورہ میں وَسَط کے معنے اعلیٰ کے ہو گئے ہیں.افسرانِ اعلیٰ بھی فوج کے درمیان ہوتے ہیں چنانچہ فوج کے کچھ دستے ان کے آگے اور کچھ پیچھے ہوتے ہیں اور وہ خود درمیان میں ہوتے ہیں کیونکہ اعلیٰ چیز کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے درمیانی چیز اعلیٰ کے معنوں میں آتی ہے.عربی زبان میں وَسِیْط اُسے کہتے ہیں جو قوم میں سب سے زیادہ شریف ہو.چونکہ اُمت محمدیہ نہ تو اُمتوں کے درمیان ہے اور نہ تعلیم میں کم ہے بلکہ فرماتا ہے کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ(اٰل عمران: ۱۱۱) تم تمام اُمتوں میں سے بہترین اُمت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو.اس لئے اس کے معنے ہیں اعلیٰ اور اکمل.
Page 531
شَھِیْدٌ کے معنے ہیں اَلشَّاھِدُ نگران(۲) اَ لْاَمِیْنُ فِی الشَّھَادَۃِ جو اپنی شہادت میں بہت سچ بولنے والا ہو.(۳) اَلْقَتِیْلُ فِیْ سَبِیْلِ اللہِ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں مارا جائے(۴) اَلْعَالِمُ الَّذِیْ لَا یَغِیْبُ عَنْ عِلْمِہٖ شَیْ ءٌ وہ عالم جس کے علم سے کوئی بات غائب نہ ہو(۵) اَلَّذِیْ یُعَایِنُ کُلَّ شَیْءٍ جو ہر چیز کو دیکھتا ہو.(اقرب) کُنْتَ: کَانَ کے ایک معنے ہیں ’’ہے‘‘ اور اس کے دوسرے معنے صَارَ کے بھی ہوتے ہیں یعنی ’’ہو گیا‘‘ اور اس کے تیسرے معنے ’’تھا ‘‘کے بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے آیت کے یہ معنے ہوںگے کہ ہم نے نہیں مقرر کیا اس قبلہ کو جس پر پہلے ُتو تھا.یا جس کی طرف ُ تو اب پھر گیا اور جس پر اب قائم ہو گیا ہے.گویا ایک معنیٰ کی رو سے تبدیلی سے پہلے قبلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے اور دوسرے معنے کی رو سے تبدیلی کے بعد کے قبلہ کی طرف اشارہ کرنا ہے.نَعْلَمَ:عَلِمَ سے نکلا ہے اور اس کے معنے جاننے کے ہیں.عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کبھی سبب کو مسبّب کی جگہ رکھ دیتے ہیں یعنی جو چیز کسی دوسری چیز کا باعث ہوتی ہے اس کو اس نتیجہ کی جگہ رکھ دیتے ہیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس کے اُلٹ بھی کر لیتے ہیں.اس جگہ سبب کو مسبّب کی جگہ رکھا ہے.علم کا نتیجہ امتیاز پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس سے انسان کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں چیز اچھی ہے یا بُری پس چونکہ تمیز علم سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اسجگہ تمیزکی بجائے علم کا لفظ رکھ دیا ہے تاکہ یہ بھی ثابت ہو کہ تمیز بغیر علم کے نہیں ہوتی (بحر محیط زیر آیت ھذا) قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں اور لغت میں بھی اس کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں جیسا کہ سماء کا لفظ بادل کے معنوں میں آجاتا ہے اس لئے کہ بادل درحقیقت بلندیوں سے اور سورج کی روشنی سے بنتے ہیں.چونکہ سماء بادل بننے کا موجب اور ذریعہ ہے اس لئے بادل کو بھی سماء کہنے لگ گئے ہیں.پس لِنَعْلَمَ کے معنے یوں ہوئے کہ ہم نے یہ کام اس غرض سے کیا تھا تاہم ان لوگوں کو جو رسول کے متبع ہیں ان لوگوں سے جو اس کی طرف سے پھر جاتے ہیں ممتاز کر دیں(۲) اس کے معنے امتیاز کرنیکی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عربی زبان میں جب عَلِمَ کے بعد مِنْ صِلہ آئے تو اس وقت بھی علم سے تمیز مراد لی جاتی ہے چنانچہ ائمہ لُغت لکھتے ہیں کہ اَلْعِلْمُ لَایَتَعَدّٰی بِـمِنْ اِلَّا اِذَااُرِیْدَ بِہِ التَّمِیْزُ(بحرمحیط زیر آیت ھذا) یعنی عِلم کا مِنْ کے ساتھ کبھی تعد یہ نہیں کیا جاتا.یعنی اسے متعدی نہیں بنایا جاتا سوائے اس صورت کے کہ اس سے تمیز مراد ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مِنْ تمیز کے لئے استعمال ہوتا ہے نہ کہ علم بمعنے جاننے کے معنے دینے کے لئے.پس جب اس کے ساتھ مِنْ آجاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ تمیز کے معنوں میں ہے (۳)علم کے معنے ظاہر کر دینے کے بھی ہوتے ہیں مگر یہ معنے عام لغات میں نہیں.جنہوں نے قرآن کریم کی لغات لکھی ہیں انہوں نے یہ معنے لکھے ہیں اور قرآن کریم سے ظاہر ہے کہ یہ معنے درست ہیں.
Page 532
عِلم کے معنے ظاہر کرنے کے سورۃ احزاب کی اس آیت میں آتے ہیں کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ ضْنَا عَلَیْھِمْ فِیْٓ اَ زْوَجِھِمْ وَمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُھُمْ(الاحزاب : ۵۱) یہاں قطعی اور یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ علم کے معنے ظاہر کرنے کے ہیں کیونکہ کوئی اپنی بات کے متعلق جاننے کا لفظ استعمال نہیں کیا کرتا.مثلاً یہ کبھی نہیں کہا جاتا کہ مجھے علم ہے کہ میں کل لاہور گیا تھا.اگر کوئی شخص ایسا کہے تو سُننے والے ہنس پڑیں گے کہ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے.پس اگر اس جگہ یہ معنے کئے جائیں کہ جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے اس کا ہمیں علم ہو گیا ہے تو یہ درست نہیں کیونکہ علم غیر کے متعلق ہوا کرتا ہے اس لئے اس کے معنے علم کے نہیں بلکہ یہ معنے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان پر فرض کیا تھا وہ ہم نے ظاہر کر دیا ہے یا بتا دیا ہے پس چونکہ اس آیت میں سوائے ظاہر کرنے اور بتا دینے کے اور کوئی معنے نہیں ہو سکتے.اس لئے یہی معنے کرنے پڑیں گے.اور یہی اِلَّا لِنَعْلَمَ کا مفہوم ہے.رَءُ وْفٌ: رَأْ فَۃٌ اور رَحْمَۃٌ دونوں قریب قریب الفاظ ہیں.مگر ان میں کچھ فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ رأفت خاص اور رحمت عام ہے.رَأْفَۃٌ میں دفع شر کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور رحمت میں دفع شر اور ایصال خیر دونوں شامل ہوتے ہیں بیمار کو دیکھ کر رأفت پیدا ہوتی ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے رحمت پیدا ہوتی ہے.کسی کو دکھ میں دیکھ کر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ رأفت کے نتیجہ میں بھی پیدا ہوتا ہے اور رحمت کے نتیجہ میں بھی پیدا ہوتا ہے.صرف اتنا فرق ہے کہ احسان رحمت سے زیادہ تعلق رکھتا ہے اور تکلیف کا دُور کرنا رأفت کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے.تفسیر.اس آیت میں كَذٰلِكَ کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اشارہ یَھْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ کی طرف ہے.یَھْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ سے یہ مضمون نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیا کرتا ہے اور اس نے تم کو اپنے فضل سے ہدایت دے دی.اب کسی کو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے اسی کی طرف کَذٰلِک میں اشارہ ہے یعنی جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اسی طرح اُس نے دوسرا احسان تم پر یہ کیا ہے کہ اس نے تمہیں اُمَّۃً وَ سَطًا بنایا ہے جیسا کہ حلِّ لُغات میں بتایا جا چکا ہے وسط کے معنے درمیان کے ہوتے ہیں لیکن اُمت محمدیہؐ نہ زمانہ کے لحاظ سے درمیانی اُمّت ہے اور نہ تعلیم اور شریعت کے لحاظ سے درمیانی امت ہے.زمانہ کے لحاظ سے تو اس لئے درمیانی امت نہیںکہ امت محمدیہؐ کے بعد اب قیامت تک اور کوئی امت نہیں پس وہ آخری امت تو کہلا سکتی ہے مگر درمیانی نہیں اور اگر شریعت کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے بھی امت محمدؐیہ درمیانی امت نہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نئی شریعت نہیں آنی کہ کہا جائے کہ کچھ شریعتیں اس سے پہلے آچکی ہیں اور کچھ بعد میں آئیں گی اور یہ اُمت
Page 533
دونوں کے درمیان ہے.اسی طرح اگر تعلیم کو لیا جائے تو قرآن کریم سب سے آخری تعلیم ہے.اس لحاظ سے بھی قرآن کریم کی تعلیم وسطی اور درمیانی نہیں کہلا سکتی.خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (المائدة:۴) یعنی آج میں نے تمہارے فائدہ کے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنے احسان کو کامل کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین کے طور پر صرف اسلام کو پسند کیا ہے پھر درجہ کے لحاظ سے بھی یہ اُمت درمیانی نہیں کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین اُمت ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّۃٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران :۱۱۱) کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے.پس اُمَّۃً وَسَطًا کے معنی یہاں درمیانی امت کے کسی صورت میں چسپاں نہیں ہو سکتے کیونکہ امت محمدؐیہ نہ تو زمانہ کے لحاظ سے درمیان میں ہے اور نہ تعلیم اورشریعت کے لحاظ سے درمیان میں ہے پس جَعَلْنٰـکُمْ اُمَّۃً وَسَطًا کے معنے یہ ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا ہے جو اپنے اعمال میں ایک وسطی رنگ رکھتی ہے اور نہ تو افراط کی طرف جھکنے والی ہے اور نہ تفریط کی طرف مائل ہونے والی ہے بلکہ اس کے اعمال ترازو کے تول کی طرح ایسے اعتدال میں رہتے ہیں کہ کوئی پہلو بھی ایک طرف جھکا ہوا دکھائی نہیں دیتا.اسی لئے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے تمام کاموں میں میانہ روی کی عادت ڈالنی چاہیے یہ نہیں کہ ایک ہی طرف کا ہو جائے اور دوسرے پہلوئوں کو نظر انداز کردے.اگر وہ ایک ہی طرف کا ہو جائے گا تو اس کے طبعی جذبات جوش میں آکر کناروں پر سے بہہ پڑیں گے.مثلاً اگر وہ رہبانیت اختیار کرےگا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کے شہوانی جذبات کسی وقت اس کو بے قابو کر دیں گے اور وہ حلال طریق کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہو جائے گا اسی طرح اگر وہ اپنا سب مال لوگوں میں تقسیم کر دےگا اور اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لئے کچھ نہیں رکھے گا تو چونکہ اس کی ضروریات خورونوش سب مال لٹا دینے سے باطل نہیں ہو جائیں گی وہ اپنا مال لٹا کر یا تو سوال کرنے پر مجبور ہو گا جو بذاتِ خود ایک ناپسندیدہ امر ہے اور یا پھر چوری اور بددیانتی کی طرف مائل ہو جائے گا اور بجائے نیکی میں ترقی کرنے کے گناہ کا مرتکب ہو گا پس شریعت اسلامی نے امت محمدیہ کو ایک ایسی امت قرار دے کر جو ہر کام میں اعتدال سے کام لیتی ہے گناہ کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے اور اُمَّۃً و سَطًا میں اسلام کی اسی وسطی تعلیم کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ دوسرے تمام مذاہب سے امتیازی شان رکھتا ہے اور اسی ایک دلیل سے اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے.اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہم نے اس لئے کیا ہےلِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم دوسرے
Page 534
مذاہب اور دوسری اقوام کے لئے ایک گواہ کی طرح رہو.یعنی جس طرح گواہ کی گواہی سے ثابت ہو تا ہے کہ حق کیا ہے اور کس کا ہے اسی طرح تم میں سے جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر کے اس کے نیک اثرات کو اپنے اندر پیدا کریں گے وہ دوسری اقوام کے لئے جو ابھی تک قرآن کریم کی صداقت سے لذت آشنا نہیں بطور ایک شاہد کے ہوں گے.یعنی زبان اور عمل دونوں سے وہ اس بات کا اعلان کرینگے کہ انہوں نے اس کے دعاوی کو سچ پایا.اور لوگ اُن کی پاکیزہ زندگی اور آسمانی نصرت کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ سچا راستہ وہی ہے جس پر یہ لوگ چلتے ہیں اور پھر آخر میں بتایا کہ جس طرح ہم نے ان مسلمانوں کو جو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں دوسری اقوام کے لئے شاہد بنایا ہے اسی طرح ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جماعت کے لئے اسلام کی سچائی کا شاہد بنایا ہے.یعنی ان کے دل میں آپ کے معجزات اور نصرتِ الہٰی کو دیکھ کر اسلام کی صداقت کامل طور پر گھر کر جاتی ہے.غرض اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ ہم نے ایسا اس لئے کیا ہے تاکہ تمہارے ساتھ خدا تعالیٰ کا معجزانہ سلوک دیکھ کر اور تمہاری روحانیت اور تقویٰ کو دیکھ کر لوگ ہدایت پائیں اور دوسری طرف یہ رسول اسلام کی سچائی کا تمہارے سامنے ایک زندہ گواہ ہو یعنی اپنے معجزات اور نصرتِ الہٰی کی بارش سے.گویا تم دنیا کے لئے اسلام کی صداقت کے گواہ ہو اور رسول تمہارے سامنے اسلام کی سچائی کا گواہ ہو.اسی طرح اس کے ایک یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ رسول تم کو اسلام سکھائے اور تم دوسروں کو سکھاتے رہو.دراصل اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی امت بننے کا یہ طریق بتایا ہے کہ وہ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ہو.یعنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے اور لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتی رہے اسی لئے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اُمَّۃً وَسَطًا بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کو سکھائو اور اُن کے نگران بنو.اور رسول کا کام ہے کہ وہ تمہیں سکھائے اور تمہاری کمزوریوں کو دور کرے.حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں تھوڑے تھوڑے عرصہ کے بعد زائد فضلے جمع ہو جاتے ہیں جو کبھی قبض کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی اسہال کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یا مکانوں اور چھتوں پر پانی کے نکاس کے راستے خراب ہو کر پانی جمع ہو جاتا اور چھتوں میں سوراخ ہونے لگتے ہیں اسی طرح قوموں پر بھی مختلف اوقات میں ایسے حالات وارد ہوتے رہتے ہیں اور جس طرح ایک زندہ انسان جسم کی کسی ایک کل کے درست ہونے سے اپنے تمام کام آپ ہی آپ نہیں چلا سکتا بلکہ صبح شام اُس کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح قوموں کے اخلاق بھی آپ ہی آپ درست نہیں ہو جاتے بلکہ صبح شام ان کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے.یہ عجیب بات ہے کہ
Page 535
فرد جس کی حیثیت قوم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں اُس کی زندگی کے لئے تو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ صبح شام نگرانی ہو.روزانہ اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ آج صبح کیا پکائیں اور شام کو کیا پکائیں.گرمی ہے تو باہر سوئیں یا سردی ہے تو اندر سوئیں.ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے تو سر کو ڈھانک کر رکھیں یا خشکی کا دورد ورہ ہے تو سر کو کھلا رکھیں.دھوپ نکلی ہوئی ہے تو سایہ میں چلیں یا بارش برس رہی ہے تو چھت کے نیچے ٹھہریں یا حبس ہے تو باہر نکل آئیں.غرض صبح شام ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں دن بھر میں انسان اپنے جسم کے متعلق پندرہ بیس دفعہ ضرور سوچتا ہے کہ اُسے اب کس چیز کی ضرورت ہے.کبھی خیال کرتا ہے کہ سونے کی ضرورت ہے کبھی خیال کرتا ہے کہ لیٹنے کی ضرورت ہے.کبھی خیال کرتا ہے کہ ورزش کی ضرورت ہے کبھی خیال کرتا ہے کہ سیر کی ضرورت ہے کبھی خیال کرتا ہے کہ نہانے کی ضرورت ہے.غرض ایک دو درجن دفعہ ضرور وہ اپنے افعال کے متعلق غور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے اپنے جسم کی درستی کے لئے کیا کرنا چاہیے لیکن قوم کی درستی کے متعلق وہ کبھی نہیں سوچتا بلکہ سمجھتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ درست ہو جائےگی.اور اگر وہ کوئی غلط قدم اُٹھا لیتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ پر الزام لگائے کہ میں نے قومی ذمہ واریوں کو ادا نہیں کیا وہ سمجھتا ہے کہ میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ قوم پر میں اپنے غصّے کا اظہار کر دوں اور عملی طور پر اس کی اصلاح کے لئے کچھ نہ کروں لیکن یہ درست نہیں.قومی درستی فردی درستی سے زیادہ توجہ چاہتی ہے اور ہر فرد کی توجہ چاہتی ہے اگر ہر فرد اس مسئلہ کی طرف توجہ نہیں کریگا تو بعض حصّوں میں ضرور نقائص پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہ اتنے بڑھ جائیں گے کہ اُن کا دُور کرنا فرد کے اختیار میں نہیں رہیگا بلکہ ایک وقت ایسا آئےگا کہ اُن کا دُور کرنا قوم کے اختیار میں بھی نہیں رہیگا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نظام قائم رکھنے کے لئے اسلام نے خلافت کا سلسلہ قائم کیا ہے لیکن غلطی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف خلافت ہی کا ذمہ ہے کہ وہ تمام کام کرے حالانکہ یہ خلافت ہی کا ذمہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایک شخص ساری قوم کی اس رنگ میں اصلاح کر سکتا ہے جب تک تمام افراد میں یہ رُوح نہ ہو کہ وہ قوم کی اصلاح کا خیال رکھیں.اور جب تک تمام افراد اس کی درستی کی طرف توجہ نہ کریں اس وقت تک اصلاح کا کام کبھی کامیاب طور پر نہیں ہو سکتا.میں سمجھتا ہوں اگر قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل میں مسلمان نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ تبلیغ ہدایت کا کام جاری رکھتے اور لوگوں کی نگرانی کا فرض صحیح طور پر ادا کرتے تو وہ کبھی تباہ نہ ہوتے.اب یہ ہماری جماعت کاکام ہے کہ وہ اس سبق کو یاد رکھے اورآئندہ نسلوں کی درستی کے لئے ہمیشہ جدو جہد کرتی رہے.غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک طرف تو تمہارا فرض ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 537
امت بھی اعلیٰ درجہ کی ہو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجہ کے لوگ نہ ملتے تو محمد رسول اللہ کی بعثت کی غرض کس طرح پوری ہوتی ؟ پس امُتِ محمدیہ کا اعلیٰ ہونا بھی ضروری تھا تاکہ وہ اسلام کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم کو اپنے اندر جذب کر کے اس کے مطابق دُنیا کی اصلاح کر سکے.اگر اس میں یہ قابلیت نہ رکھی جاتی تو اصلاح کا مقصد پورا نہ ہوسکتا.اس آیت سے اُمتِ محمدیہ میں بعثتِ مامورین کا بھی ثبوت نکلتا ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اُمتِ محمدیہ ؐ کو اس لئے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ دائمی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان لوگوں کو پہنچاتی رہے مگر چونکہ یہ خطرہ تھا کہ ایک زمانہ میں خود مسلمان ہی اس فرض سے غافل ہو جائیں گے اس لئے فرمایا کہ جب یہ فیضان مسلمانوں کی بد عملی کی وجہ سے بند ہو جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شہید بن کر دنیا میں آجائیں گے یعنی جب اُمتِ محمدیہ دوسروں کی نگرانی نہ کر سکے گی بلکہ خود نگرانی کی محتاج ہو جائیگی تو یہ رسول ہی اس کی اصلاح کریگا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یَکُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْکُمْ شَھِیْدًا کو پیچھے رکھا ہے اور لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ کو مقدّم کیا گیا ہے.اگر اس میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر ہوتا تو يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًاپہلے اور لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ بعد میں ہوتا.کیونکہ صحابہؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکھایا تھا پھر صحابہؓ نے دوسروں کو سکھایا.مگر قرآن کریم نے يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا کو پیچھے رکھا ہے اس سے صاف معلو م ہوتا ہے کہيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًاسے پہلی بعثت مراد نہیں بلکہ اس سے آپ کی دوسری بعثتیں مراد ہیں یعنی جب کبھی اُمتِ محمدیہؐ کی نگرانی میں فرق پڑ جائے گا اور مسلمانوں کا نمونہ اچھا نہیں رہےگا اُس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہید اور نگران بن کر دنیا میں آجائیں گے.اور پھر مسلمانوں کی تربیت کر کے انہیں اس قابل بنا دیں گے کہ وہ دوسروں کی تربیت کریں غرض یہ ترتیب بتاتی ہے کہ اس جگہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بروزی بعثتوں کا ذکر ہے اور الفاظ قرآنی بھی بتاتے ہیں کہ لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ سے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگ مراد نہیں بلکہ اس سے قیامت تک کے زمانہ کے لوگ مراد ہیں.پس يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا بھی قیامت تک سچا ثابت ہوتا رہےگا یعنی قیامت تک اُمتِ محمدیہ شاہد رہے گی اور قیامت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد رہیں گے.یعنی قیامت تک لوگ آپؐ سے فیضان حاصل کر کے دوسروں کو سکھاتے چلے جائیں گے اور قیامت تک محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد اور نگران کے فرائض سرانجام دیتے رہیں گے.مگر چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسمانی وجود کے ساتھ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے اس لئے یہ آیت آپ کی بعثتِ بروزی کی طرف اشارہ کرتی ہے.اور بتاتی ہے کہ اُمتِ محمدیہؐ دوسروں کی اصلاح کے لئے کھڑی کی گئی ہے لیکن جب خوداُمت محمدیہؐ میں بگاڑ پیدا ہو
Page 539
یروشلم مدینہ سے شمال کی طرف تھا اور مکہ جنوب کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیاکہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ رکھیں.چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے.وَقَدْ جَآءَ فِیْ ھٰذَا الْبَابِ اَحَادِیْثٌ کَثِیْرَۃٌ وَحَاصِلُ الْاَمْرِ اَنَّہٗ قَدْ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اُمِرَبِاِسْتِقْبَالِ الصَّخْرَۃِ مِنْ بَیْتِ الْمُقَدَّسِ فَکَانَ بِمَکَّۃَ یُصَلِّی بَیْنَ الرُّکْنَیْنِ فَتَکُوْنَ بَیْنَ یَدَ یْہِ الْکَعْبَۃُ وَھُوَ مُسْتَقْبِلُ صَخْرَۃِ بَیْتِ الْمُقَدَّسِ فَلَمَّا ھَاجَرَ اِلَی الْمَدِیْنَۃِ تَعَذَّ رَ الْجَمْعُ بَیْنَھُمَا فَاَمَرَہُ اللّٰہُ بِالتَّوَ جُّہِ اِلیٰ بَیْتِ الْمُقَدَّسِ (تفسیر ابن کثیر بر حاشیہ فتح البیان زیر آیت ھذا) یعنی تحویل قبلہ کی بحث میں بہت سی احادیث روایت کی گئی ہیں ان سب کو جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ صخرۂ بیت المقدس کی طرف منہ کریں.چنانچہ آپ مکہ میں نماز پڑھتے ہوئے ایسے طور پر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی لیکن جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ طریق جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا کریں.اس سے پتہ لگتا ہے کہ مکہ میں آپ بیت المقدس کو ہی اصل قبلہ سمجھتے تھے.بے شک آپ ایسے رنگ میں کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے آجاتا تھا مگر وہ ایک ضمنی فائدہ تھا اصل مقصد بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرنا تھا لیکن جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو جہت تبدیل ہو جانے کی وجہ سے کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف آپ کا منہ کرنا ناممکن ہو گیا اور آپ نے صرف بیت المقدس کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا.بہر حال یہ بات صحیح نہیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ ایسا کوئی حکم ثابت نہیں پس مکہ مکرمہ میں اگر بیت المقدس کے ساتھ بیت اللہ کی طرف بھی آپ کا رُخ ہوتا تھا تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آپ خانہ کعبہ ہی اپنا اصل قبلہ سمجھتے تھے صحیح نہیں.آپ بیت المقدس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے لیکن کھڑے ایسے رنگ میں ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے آجاتا.پس جب یہ بات ہی غلط ثابت ہوئی تو دشمن کا اعتراض بھی غلط ہو گیا.اسی طرح سیل کا یہ اعتراض بھی غلط ہے کہ آپ مکہ میں جدھر چاہتے منہ کر لیا کرتے تھے.اس اعتراض کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ جب آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا تو اس وقت حدیثوں میں آتا ہے کہ یہود نے تمسخر کرتے ہوئے مشرکوں سے کہا کہ اِشْتَاقَ مُحَمَّدٌ اِلیٰ مَوْلِدِہٖ وَعَنْ قَرِیْبٍ یَرْ جِعُ اِلیٰ دِیْنِکُمْ(بحر محیط زیر آیت ھذا) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپنے وطن کی یاد ستانے لگی ہے اور امید ہے کہ وہ اب جلدہی تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیگا.اس روایت سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ پہلے آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے اگر آپ پہلے بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا
Page 540
کرتے تو کفار آپ کے متعلق یہ اعتراض نہ کرتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آہستہ آہستہ مکہ والوں کے دین میں ہی شامل ہو جائے گا.ان کا یہ اعتراض اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے جبکہ آپ بیت اللہ کی طرف نہیں بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوں.علاوہ ازیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ تبدیلی فی الواقعہ کسی ذاتی فائدہ کے لئے تھی؟ معترضین کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اس غرض کے ماتحت کی گئی تھی کہ پہلے آپ نے یہودیوں کو اور بعد میں مکہ والوں کو خوش کرنا چاہا.لیکن قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ تبدیلی لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا ابتلا تھا مکہ میں مکہ کے لوگوں سے بیت المقدس کی طرف منہ کرانا اور پھر مدینہ میں جہاں یہود و نصارٰی کا زور تھا اور مشرک بھی ان سے متاثر تھے وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کرانا کوئی معمولی بات نہ تھی.اگر معمولی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا کہ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ.یعنی ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو اس سے پہلے قائم تھا یعنی بیت المقدس کو صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ تاہم اس شخص کو جو اس رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے اس شخص کے مقابل پر جوایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے ایک ممتاز حیثیت میں ظاہر کردیں.یہ آیت بتاتی ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم بطور آزمائش تھا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مکہ والوں کی نظر میں کعبہ کو جو فضیلت حاصل تھی حتّٰی کہ قاتل کو بھی اس میں کچھ نہ کہتے تھے اس کو مدِّنظر رکھتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے کہ اُن سے بیت المقدس کی طرف منہ کروانا ایک بہت بڑا ابتلاء تھا.اسی طرح مدینہ میں جہاں یہود کا زور تھا بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کروانا ایک دوسرا ابتلاء تھا اسی لئے قرآن کریم دونوں دفعہ کی تحویل کو ابتلاء قرار دیتا ہے.پہلی تحویل کی نسبت کہا ہے وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ.اور دوسری تحویل کی نسبت کہتا ہے.سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا.یعنی سطحی رائے رکھنے والے اور بے وقوف لوگ عنقریب یہ اعتراض کرینگے کہ ان لوگوں کو ایک قبلہ سے دوسرے قبلہ کی طرف کس چیز نے پھرادیا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں دفعہ کی تحویل ایک ابتلاء تھی اور لوگوں کو مغزِدین سے واقف کرنا اصل مقصود تھا.اگر معترضین کا خیال درست ہوتا کہ آپ اس ذریعہ سے مکہ والوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا.ہم تحویل قبلہ کا حکم دے کر تم پراحسان کرنے والے ہیں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں اور اسلام کی طرف ان کا میلان بڑھ جائے.مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس حکم کے نازل ہونے پر لوگ اعتراض کرینگے.اور ان کے لئے یہ تبدیلی ٹھوکر کا موجب ہو گی.گویا قرآن کریم نے تحویل قبلہ کے واقعہ کو ایک ابتلاء اور آزمائش قرار دیا ہے اسی طرح
Page 542
پر ایمان لاتے اور ہم اس گھر سے تمہارا دائمی تعلق پیدا نہ کرتے.کیونکہ اگر بیت اللہ کو قبلہ مقرر نہ کیا جاتا تو ابراہیمی پیشگوئی کی عظمت دنیا پر واضح نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ تم دُعائے ابراہیمی کے مصداق پر تو ایمان لائو اور تمہارا خانہ کعبہ کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو.اسی طرح وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ابتلاء ایمان کو ضائع کرنے کے لئے نہیں آتے بلکہ سچے ایمان کو ظاہر کرنے اور جھوٹے کے جھوٹ کو کھولنے کے لئے آتے ہیں اور اس لئے بھی آتے ہیں کہ ان سے حکمتِ احکام ظاہر ہو کر علم میں ترقی ہوتی ہے جیسا کہ تحویلِ قبلہ کے حکم سے مسلمانوں کے علم میں ترقی ہوئی.اور اگر ایک طرف ان کے ایمانوں کی مضبوطی لوگوں پر ظاہر ہوگئی تو دوسری طرف خود انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں کام کر رہی تھیں چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ اس لئے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید ابتلائوں کا آنا ایک ظلم ہے جو ایمان کوضائع کر دیتے ہیں.اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابتلائوں سے مومنوں کا ایما ن ضائع نہیں ہوتا بلکہ صرف نام نہاد مومنوں کا ایمان ضائع ہوتا ہے ورنہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ زید پختہ مومن ہو اور پھر ٹھوکر کھا جائے.وہ اگر ٹھوکر کھاتا ہے تو صرف اس لئے کہ وہ پہلے ہی صحیح معنوں میں مومن نہیں تھا.پس ابتلاء مومنوں کے ایمانوں کو ضائع کرنے کے لئے نہیں بلکہ سچے مومنوں کی روحانی عظمت اور ان کے ایمانوں کی پختگی ظاہر کرنے اور احکام الہٰیہ کی حکمت ظاہر کرنے کے لئے آیا کرتے ہیں.ریورنڈ وہیری نے اس موقعہ پر اعتراض کیا ہے کہ جب لوگوں کو ابتلاء آیا تو محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) نے نعوذ باللہ یہ بہانہ بنایا کہ یہ ایک امتحان ہے.حالانکہ یہ آیتیں تحویلِ قبلہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہیں.پس جب ابھی حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا تو ابتلاء کس کو آنا تھا.اسی طرح سَیَقُوْلُ السُّفَھَآءُ کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے کی نازل شدہ ہیں.پس وہیری کا یہ اعتراض محض تعصب پر مبنی ہے.اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حکم منسوخ نہیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاۤ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ یعنی ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو پہلے سے قائم تھا صرف اس لئے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے متعلق
Page 543
بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص حکم نازل ہوا تھا.یہ نہیں کہ آپ محض اجتہادی طور پر اہل کتاب کی اتباع میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہوں.پس اگر قرآن کریم کے احکام جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں منسوخ بھی ہوتے ہیں تو چاہیے تھا کہ وہ آیت بھی قرآن کریم میں موجود ہوتی.جس کی طر ف وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَاکے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں.مگر وہ ہے نہیں.پس ماننا پڑیگا کہ اگر قرآن کریم کا کوئی حصہ منسوخ ہوتا تھا تو پھر وہ قرآن کریم میں نہیں رکھا جاتا تھا لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ کبھی منسوخ نہیں ہوا بلکہ جو حکم منسوخ ہونا ہوتا تھا اُسے وحی متلو میں اتارا ہی نہیں جاتا تھا.بیت المقدس چونکہ عارضی قبلہ تھا اور مستقل قبلہ خانہ کعبہ بننے والا تھا.اس لئے وہ حکم قرآنی وحی سے علیٰحدہ نازل ہوا اور بعد میں منسوخ کر دیا گیا.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام احکام جن کو بعد میں منسوخ قرار دے دیا گیا تھا وہ قرآن میں نازل نہیں کئے گئے تھے.اگر وہ احکام قرآن میں موجود تھے اور پھر منسوخ کر دیئے گئے تھے تو ضروری تھا کہ وہ قرآن میں اپنی اصلی شکل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے مگر اُن کا قرآن کریم میں موجود نہ ہونا بتلاتا ہے کہ منسوخ ہونے والی وحی قرآن کریم سے علیحدہ ہوتی تھی.جیسا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم قرآن میں کہیں موجود نہیں.لیکن اس حکم کا منسوخ ہونا بتاتا ہے کہ اس بارہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور کوئی وحی نازل ہوئی تھی مگر چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس حکم نے منسوخ ہوجانا ہے اس لئے اسے قرآنی وحی میں شامل نہ کیا گیا.غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی دو قسم کی ہوا کرتی تھی ایک قرآنی اور دوسری غیر قرآنی.قرآنی وحی ہر قسم کے نسخ سے بالا تھی.مگر غیر قرآنی وحی منسوخ بھی ہو جاتی تھی جیسا کہ تحویل قبلہ کے متعلق پہلا حکم منسوخ کر دیا گیا.قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ١ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ہم تیری توجہ کا باربار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں.اس لئے ہم تجھے ضرور اُس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے تَرْضٰىهَا١۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ١ؕ وَ حَيْثُ جسے تو پسند کرتا ہے.سو (اب) تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیرلے.اور (اے مسلمانو!) تم (بھی) جہاں کہیں ہو مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ١ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا اُس کی طرف اپنے منہ کیا کرو.اور جن( لوگوں ) کو کتاب (یعنی تورات) دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں
Page 544
الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ١ؕ وَ مَا اللّٰهُ کہ یہ (تحویل قبلہ کا حکم)تیرے رب کی طرف سے (بھیجی ہوئی ایک ) صداقت ہے اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ۰۰۱۴۵ اللہ اُس سے ہرگز بے خبر نہیں ہے.حَلّ لُغَات.فَلَنُوَ لِّیَنَّکَ : وَلَّہُ الْاَمْرَ کے معنے ہیں جَعَلَہٗ وَالِیًا عَلَیْہِ اُسے فلاں پر مسلّط کردیا.(اقرب) اور وَلَّیْتُ وَجْھِیْ کَذَا کے معنے ہیں اَقْبَلْتُ.میں نے اس کی طرف اپنا منہ پھیرا.(مفردات) تفسیر.اس آیت کے متعلق بعض مفسرین روایات نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آسمان کی طرف منہ اُٹھا اُٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ تحویلِ قبلہ کا حکم کب نازل ہوتا ہے.(تفسیر ابنِ کثیر بر حاشیہ فتح البیان زیر آیت ھذا) یہ تو الگ بحث ہے کہ نماز میں اِدھر اُدھر دیکھنے سے کب روکا گیا.لیکن اس غرض کے لئے آسمان کی طرف سر اُٹھا کر دیکھنا اپنی ذات میں ایسا امر ہے جسے عقل انسانی ایک لمحہ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتی.اگر قبلہ کے علاوہ اور باتوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہوتی کہ آپ ان کے بارہ میں الٰہی حکم معلوم کرنے کے لئے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تو ہم اس امر کو بھی مان لیتے کہ شاید نماز پڑھتے وقت آپ آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے ہوں.مگر محض اس وجہ سے کہ قرآن کریم میں فِی السَّمَآءِکے الفاظ آ گئے ہیں ایک ایسے فعل کو صحیح تسلیم کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طریق عمل کے بالکل خلاف تھا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا.حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے جسے نہ سمجھتے ہوئے یہ خیال کر لیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحویلِ قبلہ کے بارہ میں آسمان کی طرف اپنی آنکھیں اُٹھا اُٹھاکر دیکھاکرتے تھے اور اس امر کے منتظر رہتے تھے کہ کب خدائی حکم نازل ہوتا ہے.ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں کہ’’ میری تونظر ہی اُدھر لگی ہوئی ہے.‘‘ یا کہتے ہیں ’’میری توجہ تو فلاں امر کی طرف پھر گئی ہے.‘‘ اور جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت ہم آنکھیں پھاڑپھاڑ کر کسی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں.اسی طرح قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِکے بھی یہی معنے ہیں کہ ہم تیری توجہ کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں.یعنی تیرے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس بارہ میں آسمان سے الہٰی حکم نازل ہو.
Page 546
قبلہ کے متعلق کوئی حکم نازل ہو چکا تھا تو پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَکے معنے کچھ نہیں بنتے.بعض لوگ اس کے یہ معنے کرتے ہیں کہ ہم تجھے والی کردیںگے (الکشاف زیر آیت ھٰذا).حالانکہ اگر اس کے یہ معنے ہوتے تو پھر یہاں قبلہ کا لفظ نہیں رکھنا چاہیے تھا بلکہ بَلَدًا یا کَعْبَۃً یا بَیْتًا کا لفظ رکھنا چاہیے تھا.کیونکہ قِبْلَۃ کا لفظ اس جگہ جہت کے معنوں میں ہے اور جہت کا کوئی والی نہیں ہوتا بلکہ کسی ملک یا شہر یامکان کا والی ہوا کرتا ہے.پس اگر نُوَلِّیَنَّکَ کے معنے والی کر دینے کے ہوتے تو پھر یوں فرمانا چاہیے تھا کہ ہم بیت اللہ یا مکہ کا تجھے والی کر دیں گے مگر خدا تعالیٰ نے قبلہ کا لفظ رکھا ہے جس کے معنے جہت کے ہیں پس یہ معنے کسی صورت میں بھی درست نہیں.علامہ ابنِ حیّان نے نُوَلِّیَنَّکَ کے معنے یہ کئے ہیں وَلَنُمَکِّنَنَّـکَ مِنْ ذٰلِکَ (بحر محیط زیر آیت ھذا ) ہم تجھے اس قبلہ پر مضبوطی سے قائم کردیں گے.یہ معنے بھی بتاتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا ورنہ قبلہ پر قائم کر دینے کے کوئی معنے ہی نہیں بنتے.نُوَ لِّیَنَّکَ تک تو ابھی وعدہ ہی تھا اس کے بعد فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فرما کر پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی بتادیا کہ صرف مدینہ میں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہو.اس کی طرف منہ کرنا یعنی یہ نہ خیال کرنا کہ چونکہ مدینہ میں بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی طرف منہ نہیں ہو سکتا.اس لئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو.جب دونوں جمع ہو سکیں تو پھر پہلے کی طرح حکم ہو گا اور دونوں کو جمع کرنا اَولیٰ ہو گا بلکہ اب یہی حکم ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کرو.بیت المقدس کا خیال رکھنا ہرگز ضروری نہیں.ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر روحانی معاملات میں اس قدر تیز تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا آپ اپنی روحانی فراست کی بنا پر اس امر پر کامل یقین رکھتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ایک نہ ایک دن ضرور نازل ہو گا.مگر دوسری طرف خدا تعالیٰ کے حکم کا ادب آپ کو اس قدر ملحوظ تھا کہ آپ نے تحویل ِ قبلہ کے متعلق کبھی دعا نہیں فرمائی.صرف آسمان کی طرف آپ نے اپنی نظریں رکھیں اور خدائی فیصلہ کے منتظر رہے.آخر آپ کی اس توجۂ روحانی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے تبدیل ِ قبلہ کے متعلق اپنا حکم نازل فرما دیا اور حکم دے دیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جاتا ہے.پھر فرماتا ہے.وَحَیْثُ مَاکُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْھَکُمْ شَطْرَہٗ اس سے پہلے فقرہ میں فرمایا تھا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِکہ تو اپنا منہ مسجدحرام کی طرف پھیردے.اور اس فقرہ میں فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو.اپنے منہ اس
Page 548
ان لوگوں کے سامنے جو اذان کی آواز سن کر بھی مسجد میں نہیں آتے کون سے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں.یا انہیں کونسی نابینائی لاحق ہوتی ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز کے لئے نہیں آتے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اندھے شخص کو بھی جو ٹھوکریں کھا کھا کر گِرتا تھا اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ گھر پر نماز پڑ ھ لے مگر آجکل لوگ معمولی معمولی عذرات کی بنا پر باجماعت نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور اس طرح اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ انہیں روحانی نابینائی لاحق ہے غرض فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَــرَامِ کہہ کر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ امامت کے متعلق احکام صرف ایک شخص کو دینے کا فی ہیں.کیونکہ باقی سارے مسلمان اس کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے اور اس طرح وہ سار ے کے سارے نماز میں شامل ہو جائیں گے.اگر کوئی کہے کہ پھر دوسری جگہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں دنیا بھر کے امام مخاطب ہیں جو ممکن ہے دس لاکھ یا دس کروڑ ہوں اور ان کی متابعت میں تمام مسلمانوں پر وہ حکم حاوی ہے.وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ.فرماتا ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی اُن پیشگوئیوں کے مطابق ہے جو اُن کی کتب میں پائی جاتی ہیں.مگر اس جگہ اہل کتاب سے صرف یہود کے مخصوص علماء مراد ہیں.جو اپنی کتب کی پیشگوئیوں سے واقف تھے ورنہ اگر تمام اہل کتاب اس بات پر یقین رکھتے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہ لاتے.ان کا ایمان نہ لانا بتاتا ہے کہ وہ دل سے آپ کی صداقت کے قائل نہیں تھے اور نہ آپؐ کو پرانی پیشگوئیوں کا مصداق تصور کرتے تھے.پس اس جگہ اَلَّذِیْنَ اُوْ تُوا الْـکِتٰبَ سے مراد صرف یہود کے وہ علماء ہیں جو اپنی کتب سے گہری واقفیت رکھتے تھے اور چونکہ قوم اپنے لیڈروں کے تابع ہوتی ہے اس لئے جب کسی قوم کے لیڈر کوئی بات سمجھ لیں تو محاورۂ زبان میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ قوم اس بات کو سمجھتی ہے.اسی رنگ میں یہاں بھی اہل کتاب سے ان کے مخصوص علماء اور لیڈر مراد ہیں.جو انبیاء بنی اسرائیل کی پیشگوئیوں سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ اب شریعت بھی بدلنے والی ہے اور قبلہ بھی تبدیل ہونے والا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسیحیوں کی دست بُرد کی وجہ سے موجودہ بائیبل میں حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے متعلق اور مکہ مکرمہ کے متعلق پیشگوئیاں وضاحت سے نہیں مل سکتیں مگر پھر بھی ان سے کچھ نہ کچھ نشان ضرور مل جاتے ہیں چنانچہ اس بارہ میں سب سے بڑی پیشگوئی وہ ہے جو استثنا باب ۳۳ آیت ۱ تا۳ میں پائی جاتی ہے.اور جس کے الفاظ یہ ہیں کہ.’’یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا نے اپنے مرنے سے آگے بنی اسرائیل کو بخشی.اور اس نے
Page 549
کہا.خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا.فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا.دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ ایک آتشی شریعت اُن کے لئے تھی.‘‘ چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ پیشگوئی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان مابہ النزاع بننے والی ہے اس لئے اس نے شروع سے ہی اس پیشگوئی میں ایسے الفاظ رکھ دیئے ہیں جن کو عیسائی اپنے اوپر چسپاں ہی نہیں کر سکتے.عیسائیت کا سارا زور اس اصل پر ہے کہ شریعت لعنت ہے (گلتیوں باب ۳ آیت ۳)لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی خبر ہی اس پیشگوئی میں یہ دی ہے کہ آنے والے موعود کے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ہو گی.پس جو قوم شریعت کو لعنت قرار دیتی ہے اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ اس پیشگوئی کو اپنے اوپر چسپاں کرے.پھر اس پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ دس۱۰ ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئے گا.مگر حضرت مسیح علیہ السلام کو دس ہزار چھوڑدس۱۰ قدّوس بھی نصیب نہ ہوئے.ان کے صرف بارہ حواری تھے ان میں سے ایک نے تو ان کو پکڑوا دیا اور دوسروں کے متعلق انجیل میں لکھا ہے کہ جب دشمن حضرت مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کے لئے آئے تو وہ سارے کے سارے انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے(متی باب ۲۶ آیت۵۶) صرف ایک حواری کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے تلوار نکال لی.اور ایک شخص پر وار کر کے اس کا کان اُڑا دیا(متی باب۲۶ آیت۵۱) مگر یہ صرف ایک عارضی جوش کا نتیجہ تھا.ورنہ اس کے بعد حواریوں نے جس ایمان کا مظاہرہ کیا اس کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے کارندے جب حضرت مسیح ؑ کو گرفتار کر کے سردار کاہن کے پاس لے گئے تو پطرس بھی ساتھ ساتھ چل پڑا.وہاں ایک لونڈی نے اُسے دیکھ کر کہہ دیا کہ تو بھی مسیح کے ساتھ تھا اس پر اس نے سب کے سامنے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں جانتا تو کیا کہتی ہے پھر دوبارہ کسی لونڈی نے یہی بات دُہرائی تو اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا.اور کہا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد پھر ان لوگوں میں سے جو وہاں کھڑے تھے کسی نے کہہ دیا کہ تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو اس کے ساتھ ہیں.اور تیری بولی سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے اس پر اس نے مسیح ؑ پر لعنت ڈالی اور قسم کھا کر کہا کہ میں مسیح کو جانتا بھی نہیں(متی باب ۲۶ آیت۶۹ تا ۷۵) غرض دس ہزار چھوڑ دس قدّوس بھی حضرت مسیح ؑکو نہیں ملے.صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے متعلق تاریخ یہ شہادت دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ فتحِ مکہ کے موقع پر دس ہزار قدوسیوں کا لشکر تھا.جو بڑے جاہ وجلال کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا اور جس نے اپنی نیکی اور عفو اور اعلیٰ درجہ کے حسنِ سلوک سے مکہ والوں کے دل فتح کر لیے اور وہ کفر و شرک کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے.(سیرت الحلبیہ جلد ۳ زیر عنوان فتح مکہ شرفہا اللہ تعالیٰ)
Page 550
تیسری خبر اس پیشگوئی میں یہ دی گئی تھی کہ ایک شریعت جدیدہ فاران کی پہاڑیوں پر ظاہر ہونے والی ہے.فاران کی پہاڑیوں سے مراد مکہ کی پہاڑیاں ہیں.کیونکہ عرب لوگ ہمیشہ سے مکہ کے پاس کے میدان کو دشتِ فاران کہتے چلے آئے ہیں فاراؔن کے معنے درحقیقت دو بھاگنے والوں کے ہیں.اور یہ نام اس جگہ کو حضرت ہاجرہؓ اور حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے جو بائیبل کے بیان کے مطابق سارہؓ کے ستانے کی وجہ سے یہاں آکر آباد ہوئے.بے شک بائیبل میں مختلف جگہوں کا نام فاران آتا ہے(پیدائش باب ۱۴ ، ۲۱.گنتی باب ۱۰ ،۱۲،۱۳.سلاطین باب ۱۱.سموئیل باب ۲۵.حبقوق باب ۳) مگر اوّل تو مختلف جگہوں کے نام فاران آنا ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ فاران کی تعیین کے لئے ضروری ہے کہ پیشگوئی کے واقعات کو ملحوظ رکھا جائے.اور دیکھا جائے کہ وہ کس فاران پر چسپاں ہوتے ہیں.اگر ایک ہی جگہ کا نام فاران ہوتا تب تو اور بات تھی لیکن چونکہ کئی مقامات کا نام فاران آتا ہے اس لئے فاران کی تعیین صرف پیشگوئی کے واقعات سے ہی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں.مثلاً اگر فاران کی پہاڑیوں سے مکہ کی پہاڑیاں مراد نہیں بلکہ کوئی اور مقام مراد ہے تو سوال یہ ہے کہ وہاں کون شخص آیا ہے جس کے ساتھ دس ہزار قدوسی تھے اور کس کے ہاتھ میں آتشی شریعت تھی اور وہ بھی اس کے داہنے ہاتھ میں.عیسائی تو بائیں ہاتھ چلو کے قائل ہیں اگر ان واقعات پر نگاہ ڈالی جائے تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے وجود ثابت ہوتے ہیں جنہیں ایک آتشی شریعت دی گئی.جو دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اور جنہوں نے ہر کام میں دائیں کو بائیں پر ترجیح دی.گویا ان واقعات نے ثابت کر دیا کہ فاران سے صرف وہی فاران مراد ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے تھے کوئی اور فاران مراد نہیں.دوم.بائیبل میں مختلف جگہوں کا نام فاران آنا یہ شبہ بھی پیدا کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی پیشگوئیوں کو مشتبہ کرنے کے لئے اس قسم کے نام رکھ دیئے ہوں گے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہود نے اپنے علماء سے سُنا کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جس کا نام محمدؐ ہو گا تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا تاکہ وہی اس پیشگوئی کے مصداق ہو جائیں.(طبقات ابن سعد جلد اوّل زیر عنوان ذکر من تسمّٰی بالجاھلیة محمد و اسد الغابة ذکر محمد بن أحیحہ) اسی طرح ممکن ہے بنی اسرائیل نے فاران کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کو دیکھتے ہوئے مختلف مقامات کا نام فاران رکھنا شروع کر دیا ہو.تاکہ آنے والا وہیں ظاہر ہو.مگر لوگوں کے خود ساختہ نام دھرے کے دھرے رہ گئے اور خدا تعالیٰ
Page 551
نے جس رسول کو مبعوث فرمانا تھا اُسے پیشگوئی کے مطابق مکہ میں مبعوث فرما دیا جس کے پاس کے میدان کو عرب لوگ ہمیشہ سے دشتِ فاران کہتے چلے آئے تھے.(۳) پھر جس پہاڑ کا نام یہود نے فاران رکھا ہے وہ بھی عرب میں ہی ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ بھی فاران کو عرب سے باہر نہیں لیجا سکے.(۴) پھر بائیبل سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ فاران سے مکہ کے پہاڑ ہی مراد ہیں.چنانچہ پیدائش باب۲۱ آیت ۲۱ میں حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے:.’’ وہ فاران کے بیابان میں رہا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت اس سے بیاہنے کو لی.‘‘ اور صرف مکہ ہی ایک ایسا شہر ہے جس کے رہنے والے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کو اپنے شہر کا بانی سمجھتے ہیں اور یہ صرف ایک روایت ہی نہیں بلکہ قوموں کی قومیں اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتی ہیں اور ان کے سب آثار وہاں پائے جاتے ہیں.بلکہ فتوحاتِ اسلام تک کعبہ میں حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے بُت بھی پائے جاتے تھے پس مکہ والوں کے دعوے کو بہر حال تسلیم کرنا پڑے گا.ورنہ یہودیوں اور عیسائیوں کو وہ شہر پیش کرنا چاہیے.جس کی بنیاد حضرت ابراہیم ؑ اور حضرت اسمٰعیل ؑ نے رکھی ہو اور جس کے رہنے والے اپنے آپ کو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوں.اور اگر کوئی ایسا شہر پیش نہ کر سکیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہی وہ فاران ہے جس کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی.اس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رہنا ثابت ہے اور پھر اسی جگہ کے متعلق مکہ والے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہاں رہے اور یہیں ان کے آثار پائے جاتے ہیں لیکن وہ جگہ جسے یہودی اور عیسائی فاران قرار دیتے ہیں اس میں رہنے والے لوگ یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہاں حضرت اسمٰعیل ؑ آکر رہے تھے.حالانکہ لوگ فخر حاصل کرنے کے لئے بلا وجہ بھی ایسی باتوں کو اپنی طرف منسوب کرلیتے ہیں.(۵) پھر وہ چشمہ جو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے لئے خدا تعالیٰ نے نکالا تھا وہ بھی مکہ ہی میں ہے جو اس بات کا ایک یقینی اور قطعی ثبوت ہے کہ حضرت اسمٰعیل ؑاور حضرت ہاجرہ ؑ یہیں آکر آباد ہوئے تھے.پھر انجیل میں بھی ایک پیشگوئی قبلہ کے بدلنے کے متعلق پائی جاتی ہے.یوحنا باب۴ آیت ۲۰،۲۱ میں لکھا ہے کہ ایک سامری عورت نے جس سے مسیح نے پانی مانگا تھا کہا کہ ’’ہمارے باپ دادوں نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے یسوع نے اس سے کہا اے عورت! میری بات کا یقین رکھ کہ وہ گھڑی آتی ہے
Page 552
کہ جس میں تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے.‘‘ اس پیشگوئی میں حضرت مسیح صاف الفاظ میں اعلان فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میں نہ یہ پہاڑ قبلہ رہے گا اور نہ یروشلم بلکہ ان دونوں کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ ایک تیسرا قبلہ مقرر کرے گا.ان آیات میں جو پہاڑ پر اور یروشلم میں پرستش کرنے کا ذکر ہے اس سے یہ مراد نہیں کہ یہود سب یروشلم میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور سامری اس پہاڑ پر عبادت کرتے تھے بلکہ اس سے یروشلم اور اس پہاڑ کو قبلہ بنانا ہی مراد ہے یعنی وہ ان کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے پس پہاڑ پر اور یروشلم میں عبادت نہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آئندہ ان کی طرف منہ کر کے عبادت نہیں کی جائے گی.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح انجیل نے پہاڑ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کو پہاڑ پر عبادت کرنے کے الفاظ سے ادا کیا ہے اسی طرح قرآن کریم نے بھی قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ کا محاورہ استعمال کیا ہے جس سے مراد آسمان کی طرف آپ کا منہ کرنا نہیں بلکہ آسمان کی طرف آپ کی توجہ کا مبذول ہونا مراد ہے.ان دو پیشگوئیوں کے علاوہ اور بھی بہت سی پیشگوئیاں ہیں جو کعبہ کی ترقی پر دلالت کرتی ہیں مگر مثال کے طو ر پر یہ صرف دو ہی کافی ہیں پس ان پیشگوئیوں کی بنا پر گو یہود پہلے ان کا مطلب نہ سمجھتے ہوں مگر وقوع کے بعد ان کے لئے اس امر کا سمجھنا کچھ بھی مشکل نہ تھا کہ یہ حکم ایک قدیم پیشگوئی کے مطابق ہے اور اس پر اعتراض کرنا اپنی کتب پر اعتراض کرنا ہے.اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ میں اہل کتاب سے مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں.اس لحاظ سے اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کامل کتاب عنایت فرمائی ہے وہ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا جو حکم دیا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے نہ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو گا.بلکہ اس لئے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں.اور ان پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے.ایسی صورت میں یہ ناممکن تھا کہ وہ آپ کے احکام کو منجانب اللہ نہ سمجھیں اور آپ ؐ کی ہر رنگ میں کامل اطاعت نہ کریں.وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ.فرماتا ہے.ہم ان کی حرکات کو خوب جانتے ہیں.ان کے بڑے بڑے علماء محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہونے کے باوجود محض ضِد اور تکبر کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں ورنہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تبدیلی اور بنو اسمٰعیل میں ایک نبی کے آنے کے متعلق ان کی کتابوں میں پیشگوئیاں
Page 553
موجود ہیں مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہوتے.تحویل قبلہ ہجرت کے بعد کوئی سولہ یا سترہ مہینے گذرنے پر ہوئی ہے.چنانچہ بخاری میں حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے کے بعد سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن آپ کو پسند یہی تھا کہ قبلہ بیت اللہ ہو.آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بارہ میں حکم نازل ہوا اور آپؐ نے پہلی نماز جو کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی.ایک شخص جو نماز میں آپ کے ساتھ شامل ہوا تھا.وہ نماز سے فارغ ہو کر ایک مسجد کے پاس سے گذرا.تو اس نے دیکھاکہ لوگ رکوع کی حالت میں ہیں.اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس پر اس نے بلند آواز سے کہا.کہ اَشْھَدُ بِاللّٰہِ لَقَدْ صَلَّیْتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَکَّۃَ.یعنی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے.اس پر لوگوں نے نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس سے منہ ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لیا.(بخاری کتاب التفسیر باب قولہ سیقول السفہاء و تفسیر ابن کثیرزیر آیت سیقول السفھآء) نسائی نے ابو سعیدؓ سے روایت کی ہے کہ ظہر کی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ ہوئی.ابو سعید ؓ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ساتھی پہلے لوگ ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی.اور کئی مفسرین نے اور بعض دوسرے راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ظہر کی نماز کی دو رکعتیں ہو چکی تھیں جبکہ یہ حکم نازل ہوا.یہ حکم مسجد بنی سلمہ میں نازل ہوا تھا.اسی لئے صحابہ ؓ اس مسجد کو مسجد القبلتین کہتے تھے.( تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھٰذا) اوپر کی روایات سے ظاہر ہے کہ ایک میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ عصر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوئی اور دوسری میں یہ ذکر آتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم ظہر کی نمازمیں نازل ہوا.ظہر والی روایات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تحویل قبلہ تو ظہر کے وقت ہوئی ہو اور ایک شخص عصر کی نماز میں آکر شامل ہوا ہو اور اس نے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھ کر یہ سمجھ لیا ہو کہ تحویل اب ہوئی ہے کیونکہ عصر کے وقت آنے والے کا خیال ظہر کی نمازکی طرف نہیں جا سکتا پس ظہر والی روایت کو ترجیح دی جائےگی.نویلہ بنت مسلم کی روایت ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ خبر آئی کہ بیت اللہ قبلہ ہو گیا ہے.یہ بھی پہلی روایت کی تائید کرتی ہے چنانچہ لکھا ہے کہ مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ ہو گئیں(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھٰذا)
Page 554
یہ اسلامی حکم ہے کہ مرد آگے ہوں اور عورتیں پیچھے.تحویل قبلہ کی وجہ سے چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رُخ بدلنا پڑا اس لئے مردوں اور عورتوں کو بھی اپنی ترتیب بدلنی پڑی.اور عورتیں مردوں کی جگہ چلی گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے.اس حدیث میں ایسی تفصیل موجود ہے جس کی بناپر ظہر میں حکم نازل ہونے کا خیال زیادہ صحیح قرار پاتا ہے.یہ بھی لکھا ہے کہ اہل قبا کو دوسرے دن صبح کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ نماز کی جہت بدل گئی ہے.اور وہ بھی اس وقت جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے.(بخاری کتاب التفسیر باب قولہ وما جعلنا القبلۃ ) اسی سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ اگر ایک میل کے فاصلہ پر بھی دوسرے دن اطلاع پہنچی تو براء بن عازب کو بھی عصر کی تعیین میں غلطی لگ سکتی ہے انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ عصر کے وقت تحویل قبلہ ہوئی ہے کیونکہ انہیں عصر کی نماز میں ہی شامل ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے کسی سے دریافت بھی نہ کیا کہ تحویلِ قبلہ کب ہوئی ہے.خود ہی خیال کر لیا کہ یہ پہلی نماز ہے جس میں تحویلِ قبلہ ہوئی ہے.ان روایات میں بھی یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکر بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا.ورنہ اگر یہ بات درست ہوتی تو جو لوگ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے وہاں آچکے تھے.ان میں سے کسی کی تو روایت ملتی کہ وہ پہلے مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے.حقیقت یہی ہے کہ آپ مکہ میں بھی بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے اور پھر مدینہ میں بھی سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے.پس وہیری کا یہ اعتراض کہ محض یہود کو خوش کرنے کیلئے آپ نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا اور جب یہ مقصد حاصل نہ ہوا تو پھر مکہ کی طرف منہ پھیر لیا بالکل غلط ہے.صرف ایک روایت ایسی ہے جو بتاتی ہے کہ نعوذ باللہ یہود کو خوش کرنے کے لئے مدینہ آکر قبلہ بدلا گیا.مگر اس روایت کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کسی بد باطن منافق یا یہود کی خود تراشیدہ روایت ہے.یہ روایت ابودائود نے اپنی کتاب ناسخ میں حضرت ابن عباسؓ سے بیان کی ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ.اَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْقِبْلَۃُ وَذٰلِکَ اَنَّ مُحَمَّدًا کَانَ یَسْتَقْبِلُ صَخْرَ ۃَ بَیْتِ الْمُقَدَّسِ وَھِیَ قِبْلَۃُ الْیَھُوْدِ فَاسْتَقْبَلَھَا سَبْعَۃَ عَشَرَ شَھْرًا لِیُؤْمِنُوْا بِہٖ وَیَتَّبِعُوْہُ وَیَدْ عُوْا بِذٰلِکَ الْاُمِّیِّیْنَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَیْنَمَـا تُوَ لُّوْا فَثَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ (جامع البیان زیر آیت ھٰذا).یعنی قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم جو منسوخ کیا گیا وہ قبلہ کے بارے میں تھا اور یہ کہ محمد( صلی اللہ علیہ وسلم) مدینہ میں تشریف لانے کے بعد صخرۂ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے جو یہود کا قبلہ تھا.اور آپؐ نے اُس کی طرف سترہ مہینے تک منہ رکھا.آپؐ کی بیت المقدس کو
Page 557
نے یہ کہنا شروع کر دیا قَدِ اشْتَاقَ الرَّجُلُ اِلٰی بَلَدِہٖ وَبَیْتِ اَبِیْہِ (بہیقی جلد ۲ باب تحویل قبلہ)یعنی یہ شخص پھر اپنے وطن اور اپنے باپ دادا کے گھر کا مشتاق ہو گیا ہے.ابن کثیر نے یہ الفاظ درج کئے ہیں کہ قَدِ اشْتَاقَ الرَّجُلُ اِلٰی بَیْتِ اَبِیْہِ وَ دِیْنِ قَوْمِہٖ.(تفسیرابن کثیر زیر آیت ھذا)یعنی یہ شخص اپنے باپ دادا کے گھر اور اپنی قوم کے دین کا مشتاق ہو گیا ہے.اس روایت سے بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیرنا یہودیوں پر سخت گراں گذرا تھا.اور وہ بڑے زور سے یہ اعتراض کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کبھی اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی اُس قبلہ کی طرف اور اسی طعنہ زنی کے شوق میں انہوں نے وہ روایت وضع کر لی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے.بہر حال اس روایت سے صاف طور پر پتہ لگتا ہے کہ سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا والی آیات قبلہ کے بدلنے کے حکم اور یہود کے اعتراض کے بعد نازل نہیں ہوئیں بلکہ پہلے نازل ہوئی تھیں.چنانچہ بعد میں تحویلِ قبلہ کا حکم نازل ہونے پر یہود نے بھی اعتراضات کئے اور بعض مسلمانوں کے قدم بھی لڑکھڑا گئے اور وہ مرتد ہو گئے.یہ مضمون عام تفاسیر کے خلاف ہے لیکن اوپر کی روایت سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ والی آیات پہلے اعتراضات کے جواب میں نہیں بلکہ ان اعتراضات کے ردّ میں تھیں جو بعد میں لوگوں نے کرنے تھے اور جن کی قبل از وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئی کر دی گئی تھی.وَ لَىِٕنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا اور جن لوگوں کو (تم سے پہلے) کتاب دی گئی ہے اگر تو اُن کے پاس ہر ایک (طرح کا) نشان (بھی) لے آئے قِبْلَتَكَ١ۚ وَ مَاۤ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ١ۚ وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ (تو بھی) وہ تیرے قبلہ کی پیروی نہ کریں گےاور نہ تو اُن کے قبلہ کی پیروی کر سکتا ہے اور نہ اُن میں سے قِبْلَةَ بَعْضٍ١ؕ وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ کوئی (فریق) دوسرے (فریق) کے قبلہ کی پیروی کرے گا اور (اے مخاطب) اگر اس کے بعد بھی کہ تیرے پاس
Page 559
کرتے.پس آپ کے اِس فعل نے ثابت کر دیا کہ آپ کو ان سے کوئی ضِد نہیں تھی.ہاں یہود کے فعل نے یہ ثابت کر دیا کہ اُن کو ضِد تھی.کیونکہ انہوں نے تبدیل قبلہ کے متعلق اپنی کتب میں واضح پیشگوئیاں دیکھنے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا.غرض دو۲ وجوہ سے آپؐ پر اعتراض نہیں پڑ سکتا.اول اس وجہ سے کہ آپؐ نے سالہا سال تک بیت المقدس کی طرف منہ کیا.پس آپؐ کے متعلق نہیں کہا جا سکتا کہ آپؐ میں ضِد پائی جاتی تھی.دوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا تو یہ الہام الہٰی کے ماتحت کیا تھا لیکن یہود نے محض ضِد کی وجہ سے اس کا انکار کیا نہ کہ الہام الہٰی کی وجہ سے اس لئے آپؐ کے فعل کو ان کے فعل سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی.وَ مَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ.اب اللہ تعالیٰ اُن کی ضِد کو اور زیادہ واضح کرنے کے لئے فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے قبلہ کی بھی پیروی نہیں کرتے.دراصل یہودیوں اور عیسائیوں کے قبلہ میں بھی فرق ہے یہود کا قبلہ تو یروشلم تھا.جیسا کہ نمبر ۱ سلاطین باب ۸ آیت۲۲ تا ۳۰ اور دانیال باب۶ آیت۱۰ سے ظاہر ہے لیکن یہود کا سامری فرقہ یروشلم کے ایک پہاڑ کی طرف اپنا منہ کیا کرتا تھا جیسا کہ انجیل میں لکھا ہے.حضرت مسیح ؑنے ایک سامری عورت سے کہا کہ ’’میری بات کا یقین رکھ کہ وہ گھڑی آتی ہے کہ جس میں تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے.‘‘ (یوحنا باب ۴ آیت ۲۱) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں کم از کم دو۲ فریق تھے ایک وہ جو یروشلم کے پہاڑ کی طرف منہ کرتے تھے اور دوسرے وہ جو یروشلم کی طرف منہ کرتے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے زمانہ میں عیسائی مشرق کی طرف اور یہود بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے.چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو دورانِ بحث میں اُن کی عبادت کا وقت آگیا.اس پر انہوں نے مسجد نبویؐ میں ہی مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنے طریق کے مطابق عبادت کرلی.حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فَاسْتَقْبَلُوا الْمَشْرِقَ فَصَلُّوْا صَلٰوتَھُمْ (شرح زرقانی الفصل العاشر فی ذکر من وفد علیہ...الوفد الرابع )یعنی انہوں نے مسجد میں ہی مشرق کی طرف منہ کیا اور اپنی عبادت بجا لائے.یہ روایت بتاتی ہے کہ اس زمانہ میں عیسائی مشرق کی طرف منہ کیا کرتے تھے.مشرق کی طرف منہ کرنے کی وجہ بقول پادری اکبر مسیح یہ تھی کہ چونکہ مشرق میں خداوند مسیح کا ستارہ دیکھا گیا تھا اور خداوند کی پیدائش و حیات و وفات و قیامت سب ارض مقدس میں ہوئیں اس لئے مشرق اور اس ملک کی طرف منہ پھیرنا ان کو محبوب رہا(سلکِ مروارید حصہ اوّل صفحہ ۴۵ ) اس
Page 560
بارہ میں مزید تشریح کے لئے دیکھیں تفسیر کبیر تفسیر سورہ مریم زیر آیت اِذِا انْتَبَذَ تْ مِنْ اَھْلِھَا مَکَانًا شَرْقِیًّا.غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تمہاری بات کیا ماننی ہے ان میں تو اس قدر تعصب پایا جاتاہے کہ ایک کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے بھی ان کے قبلوں میں فرق ہے.اور جب یہ آپس میں ایک شریعت رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی ضد میں دین کی شکل بدلتے جاتے ہیں تو انہوں نے تمہاری طرف کیا میلان رکھنا ہے.وَ لَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر علم رکھنے کے بعد بھی تو ان کی گری ہوئی خواہشات کی پیروی کریگا تو تُو یقیناً ظالم ہو گا.اس آیت پر بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ممکن تھا کہ آپؐ ان کی خواہشات کی پیروی کر کے ظالم بن جاتے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بعض جگہ بظاہر واحد مخاطب کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے مگر اس سے ہر انسان مراد ہوتا ہے نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم.قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا (بنی اسرائیل :۲۴) یعنی اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو تم ان سے نرمی کا برتائو کرو اور انہیں اُف بھی نہ کہو.اب اس آیت میں بھی واحد مخاطب کی ضمیر استعمال کی گئی ہے.حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس جگہ ہر انسان کو مخاطب کیا گیا ہے.نہ کہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو.اسی طرح اس آیت کے یہ معنے ہیں کہ اے قرآن کریم کے پڑھنے والے اگر تو مخالفین اسلام کی گِری ہوئی خواہشات کی پیروی کریگا تو تُو ظالم بن جائے گا.کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایک یقینی علم نازل کر دیا ہے.اگر تو اس سے فائدہ نہیں اُٹھائے گا اور اسے چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے چلے گا تو تُو اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا.ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماچکا ہے کہ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَھُمْ تو ان کے قبلہ کی کبھی پیروی نہیں کر سکتا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ اتنی وضاحت سے ایک بات فرما چکا ہے تو اسی آیت میں اس کے خلاف یہ کیونکر فرما سکتا ہے کہ اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تُو ظالموں میں سے سمجھا جائے گا.پس اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ عام مسلمان مراد ہیں.چنانچہ آجکل ایسا ہی ہورہا ہے کہ مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ کر دوسرے علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ روزانہ بدلتے ہیں.اور اس یقینی علم کو انہوں نے ترک کر دیا ہے.جو قرآن کریم کی شکل میں ہے.
Page 561
پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ جب مقدمہ کا فیصلہ لکھواتا ہے تو بعض مقامات پر اس میں مجرم کے خطاب کے الفاظ استعمال کرتا ہے.مثلاً وہ کہتا ہے.اس جرم میں تجھے اتنے ماہ قید کی سزا دی جاتی ہے اس پر تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ فیصلہ کو قلمبند کرنے والا کلرک کھڑے ہو کرشور مچانے لگ جائے کہ مجھے یہ سزا کیوں دی گئی ہے.اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کا اعلان فرمایا ہے اور اس سے مراد صرف وہی شخص ہے جو اس فیصلہ کی خلاف ورزی کرے کوئی دوسرا شخص مراد نہیں ہو سکتا.اسی طرح کبھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ حکم دیتے وقت اپنے کسی قریبی کو مخاطب کرلیا جاتا ہے مگر مراد اس سے دوسرے لوگ ہوتے ہیں اور اس کو مخاطب اس لئے کیا جاتا ہے کہ اگر میر ا قریب ترین عزیز بھی ایسا کرے گا تو میں اُسے سزا دوںگا.یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ قریبی ایسا کر سکتا ہے بلکہ اس سے جرم کی اہمیت بیان کرنا اور لوگوں کو ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے.اس جگہ بھی یہ مراد نہیں کہ ایسا کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممکن تھا بلکہ آپؐ کو اس لئے مخاطب کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کو ہوشیار کیا جائے اور انہیں متنبہ کیا جائے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی ایسا کرے گا تو اسے سزا ملے گی.اور اس کا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا.یہ بھی ہوشیار کرنے کا ایک طریق ہوتا ہے.جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے ایک موقعہ پر فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہؓ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں(بخاری کتاب الحدود باب کراھیۃ الشفاعۃ فی الحدّ...).اب اس کا یہ مطلب نہیںتھا کہ حضرت فاطمہؓ بھی چوری کر سکتی تھیں.بلکہ مطلب یہ تھا کہ دوسرے لوگ ہوشیار ہو جائیں.اور انہیں پتا لگ جائے کہ قانون میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں کیا جا سکتا.اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ١ؕ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (سچائی) کو (اسی طرح) پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.وَ اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ۰۰۱۴۶ اور اُن میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں.تفسیر.اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل کتاب کی نسبت فرماتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے.بیٹے کی پہچان ہمیشہ بیوی کی شہادت پر ہوتی ہے.جب
Page 563
چھپا رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر کمر بستہ ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کادوست تو (نعوذباللہ) پاگل ہو گیا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے.کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں.حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اُسی وقت اُٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کے دروازہ پر دستک دی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے.تو حضرت ابوبکر ؓ نے عرض کیا کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں.کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو ان کو ٹھوکر لگ جائے تشریح کرنی چاہی.مگر حضرت ابوبکرؓ نے کہا.آپؐ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپؐ نے یہ بات کہی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خیال سے کہ معلوم نہیں یہ سوال کریں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح نازل ہوتے ہیں؟ پہلے کچھ تمہیدی طور پر بات کرنی چاہی.مگر حضرت ابوبکرؓ نے پھر کہا.نہیں نہیں آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ آپؐ نے فرمایا.ہاں درست ہے.اس پر حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا.میں آپ پر ایمان لاتا ہوں.اور پھر انہوں نے کہا یارسول اللہ! میں نے دلائل بیان کرنے سے صرف اس لئے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان مشاہدہ پر مبنی ہو.دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو کیونکہ آپ کو صادق اور راستباز تسلیم کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی.غرض جس بات کو مکہ والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت ابوبکرؓ نے اپنے عمل سے واضح کر کے دکھادیا.اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَؒ۰۰۱۴۸ یہ (مذکورہ بالا) صداقت تیرے رب کی طرف سے ہے.پس تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بن.حلّ لغات.اِمْتَرَاءٌ کے معنے ہیں (۱) جھگڑا کرنا (۲) شک کرنا.(المنجد) تفسیر.فرماتا ہے.یہ صداقت تیرے رب کی طرف سے ہے اور اس نے دنیا میں ایک دن پھیل کر رہنا ہے.جس بات کے پورا ہونے کے متعلق انسان کو شبہ ہو اس کے متعلق تو وہ بہانہ بنا سکتا ہے کہ شاید وہ ٹل جائے لیکن ہمارا رسول تو جو کچھ کہتا ہے وہ ایک اٹل صداقت ہے جو ایک دن پوری ہو کر رہے گی.اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ یہ حق
Page 564
تمہارے رب کی طرف سے ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے.اور جس نے درجہ بدرجہ تمہیں ترقی دیتے ہوئے اس بلند مقام تک پہنچایا.کیا ایسی اعلیٰ درجہ کی ربوبیت کرنیوالی ہستی کا کلام کبھی ٹل سکتا ہے پس اس کو ردّ کرنے کا کیا فائدہ.اس سے تو تمہارا ہی نقصان ہو گا.تم اگر ردّ بھی کرو گے تو یہ تعلیم ضرور پھیل کر رہے گی اس لئے اس کے انکار سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا.میں ابھی چھوٹا تھا کہ میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک سٹرک پر جو مدرسہ احمدیہ کے پاس سے مہمان خانہ کو جاتی ہے.کبڈی ہو رہی ہے.لکیر جو حدِ فاصل ہوتی ہے کھینچی ہوئی ہے اور ہم ایک طرف ہیں اور غیر احمدی دوسری طرف.غیر احمدیوں میں سے جوبھی ہماری طرف آتا ہے ہمارے آدمی اسے پکڑ کر بٹھا لیتے ہیں حتیّٰ کہ ان کے سارے آدمی ہماری طرف آگئے صرف مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی پیچھے رہ گئے.اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی دیوار کی طرف منہ کر کے آہستہ آہستہ ہماری طرف چلنا شروع کیا اور جب لکیر پر پہنچے تو کہنے لگے کہ جب سارے ہی آگئے ہیں تو میں بھی آجاتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ بھی ہماری طرف آگئے.یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ یہ صداقت تو دنیا میں غالب آنےوالی ہے اور جب آخر میں تم نے ایمان ہی لانا ہے تو آج ہی کیوں نہیں مان لیتے.چنانچہ دیکھ لو آخر مشرکین مکہ فتح مکہ کے دن آپؐ کے پاس آئے اور منتیں کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے.آپؐ نے فرمایا جائو.لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ.آج میں تمہیں کوئی سرزنش نہیں کرتا.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے.ع قضائے آسماں است ایں بہر حالت شود پیدا (آئینہ کمالات اسلام ،روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۲) یعنی یہ تو ایک آسمانی قضا ہے اور اس نے ضرور پورا ہونا ہے.پھر تم انکار کر کے اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو.خ خ خ خ