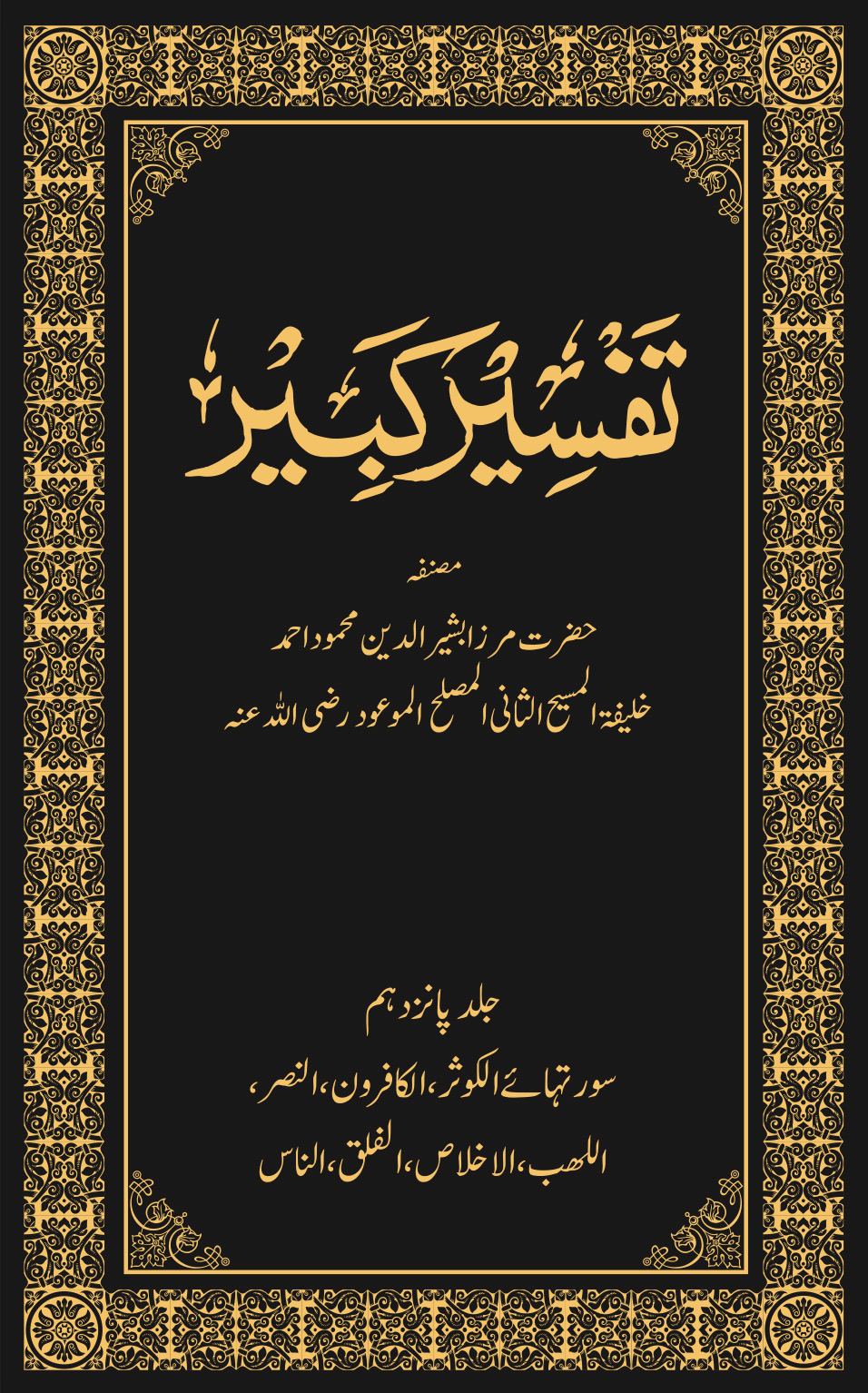Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 15
Content sourced fromAlislam.org
Page 5
سُوْرَۃُ الْکَوْثَرِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ کوثر.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ ثَلٰثُ اٰیَا تٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اوراس کی بسم اللہ کے علاوہ تین آیات ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ کوثر مکی سورۃ ہے سورۃ کو ثر اکثر رواۃ کے نزد یک مکی سورتوں میں سے ہے.حسن بصری ؒ، عکرمہؓ اور قتادہ اسے مدنی قرار دیتے ہیں.یوروپین مستشرقین کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے اور اسلام کے بالکل ابتدائی زمانہ کی ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ آپ کو نعوذباللہ دیوانہ سمجھتے تھے اور اس لئے وہ آپ سے کچھ سرو کار نہیں رکھتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ شخص عرب کے قومی مذہب کو بگاڑنے کی تدبیریں کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا چا ہیے، اس لئے وہ آپ کو ایذائیں دیتے، دکھ دیتے اور مارتے پیٹتے تھے.پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) کی تم مخالفت کروگے اور اسے مارو پیٹو گے تو خواہ مخواہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہو گی.کیونکہ باہر کے لوگ مکہ آتے ہیں جب وہ دیکھتےہیں کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)کو ایذائیں دیتے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو تو وہ اس کے متعلق پوچھنے لگ جاتے ہیں اور اس کے معاملہ میں دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں.اس طرح اسے اہمیت اور عظمت حاصل ہوتی جارہی ہے.گو اس کی باتیں ہمیں پسند نہیں ہیں.گو اس کی تعلیم سارے عرب کے قومی مذہب کے خلاف ہے مگر مصلحتاً ہمیں اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے تا اسے اہمیت و عظمت حاصل نہ ہو جائے ان لوگوں میں سے عاص بن وائل بھی تھا جو مکہ کا ایک بڑا سردار تھا.اس کا بھی یہی خیال تھا کہ مخالفت کی وجہ سے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت حاصل ہورہی ہے اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو رہی ہے اس لئے ہمیں مخالفت سےرک جانا چاہیے اور انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے.اگرچہ ہمیں ان کی حرکات پسند نہیں اور اگرچہ ان کی تعلیم ہمارے مذہب کے خلاف ہے.مگر پھر بھی مصلحت اسی میں ہےکہ انہیں کچھ نہ کہیں.چنانچہ عاص بن وائل کہا کرتا تھا کہ دَعُوْہُ اِنَّـمَاھُوَ رَجُلٌ اَبْتَـرُ لَا عَقِبَ لَہٗ لَوْ ھَلَکَ انْقَطَعَ ذِکْرُہٗ وَاسْتَـرَحْتُمْ مِنْہُ (البحر المحیط سورۃ الکوثر) یعنی محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو
Page 6
چھوڑ دو یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی پیچھےرہنے والا ہے جو اس کی تعلیم کو اس کی وفات کے بعد قائم رکھ سکے.اگریہ وفات پا گیا تو اس کا ذکر خود بخود منقطع ہو جائے گا اور تم اس کے وعظوں اور نصیحتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے.مفسرین کے نزدیک سورۂ کوثر کا شانِ نزول گویا عاص بن وائل کے نزدیک آپ کی تعلیم ایک جتھہ بندی والی بات تھی اور نرینہ اولاد ہی اس کو قائم رکھنے میں ممدّ ہو سکتی تھی.چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں اور لڑکیوں کی عرب میں کوئی وقعت نہیں سمجھی جاتی تھی.عرب لوگ سمجھتے تھے کہ لڑکیاں تو دوسرےخاندانوں میں چلی جائیں گی جہاں وہ انہی کی مرضی کےمطابق چلیں گی.باپ کی یاد کو قائم رکھنے والے تو اس کےلڑکے ہی ہو تے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نرینہ اولاد نہیں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں اس لئے جب آپ وفات پا جائیں گے تو آپ کی تعلیم بھی ختم ہو جائے گی خواہ مخواہ آپ کی مخالفت کر نے میں آپ کو اہمیت حاصل ہو تی جا رہی ہے.انہیں چھوڑ دو.وفات کے بعد آپ کا قائم کردہ سلسلہ خودبخود منقطع ہو جائے گا پس مخالفت کر کے آپ کی تعلیم پھیلانے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ مخالفت کو دیکھ کر لوگوں کی توجہ خواہ مخواہ ان کی طرف پھر جاتی ہے.اسی وجہ سے عاص بن وائل یہ کہا کرتا تھا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نرینہ اولاد نہیں جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے سلسلے کو قائم رکھ سکے.مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اس کے ہم خیال لوگوں کی تردید میں ہی یہ سورۃ اتاری.تاریخوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کو ابتر کہنے والا صرف عاص بن وائل ہی نہیں تھا بلکہ اور لوگ بھی تھےجو آپ کو ابتر کہاکرتے تھے.ابو جہل کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی آپ کو ابتر کہا کرتا تھا.اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سب کی نرینہ اولاد تھی، لڑکے تھے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا نہیں تھا اور جتھہ بندی کے لحاظ سے عرب میں لڑکے کی قدر ہو تی تھی ان لوگوں کا خیال تھا کہ جب آپ وفات پا جائیں گے تو ساتھ ہی آپ کا قائم کردہ سلسلہ بھی ختم ہوجائے گا.وہ آپ کے سلسلہ کو عارضی شورش سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں مخالفت سے خواہ مخواہ اس سلسلہ کو ترقی مل رہی ہے.سورۂ کوثر کو مدنی کہنے والوں کی تردید اس سورۃ میں چونکہ ایسے لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے.اس لئے بعض لوگوں نے غلطی سے اسے مدنی قرار دے دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے اس وقت کفار نے یہ کہا تھا کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں
Page 7
اور اس وقت یہ سورۃ ان کے خیال کی تردید میں نازل ہوئی تھی.(روح المعانی زیر آیت اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ) لیکن جب روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے تو محض ابتر کے لفظ سے یہ قیاس کر لینا کہ یہ سورۃ مدنی ہے درست نہیں.کفار آپ کے بیٹے ابراہیم کی پیدائش تک کیوں خاموش رہے تھے.ابراہیم آپؐکی وفات سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تھے گویا آپ کی وفات سے تین سال قبل تک آپ کو کوئی بھی ابتر نہیں کہتا تھا.کون عقلمند یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو اور وہ وفات پائے تو پھر آپ کو ابتر کہیں.ابراہیم کی پیدائش سے پہلے بیس سال میں بھی تو آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اور پھر آپ پر بڑھاپا بھی آیا ہوا تھا.اس وقت کفار نے آپ کو ابتر کیوں نہیں کہا.جب ابراہیم کی پیدائش تک وہ انتظار کرتے رہے تو اس کی وفات کے بعد انہوں نے کیوں انتظار نہیں کیا.ابراہیم ڈیڑھ سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے تو کیا اس کے بعد آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہوسکتی تھی.کیا ڈیڑھ سال کے عرصہ میں انسان ناکارہ ہو جاتا ہے؟ یہ محض قیاسات ہیں عقل ان کی تائید نہیں کرتی.یہ سورۃ میرے مقرر کردہ اصول کے مطابق (جو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم کی آخری چند سورتوں میں سے باری باری ایک سورۃ زیادہ تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری زیادہ تر آپ کی امت کے آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہے) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے.یہ ضروری نہیں کہ جو سورۃ آپؐکے ابتدائی زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہو اس میں آپؐکی امّت کے آخری زمانہ کا ذکر نہ ہو یا جو سورۃ آپؐکی امت کے آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہو اس میں آپ کے ابتدائی زمانہ کا ذکر نہ ہو ذکر تودونوں زمانوں کا پایا جا سکتا ہے.لیکن مضمون میں زیادہ تر اہمیت ابتدائی زمانہ کو ہو گی یا آخری زمانہ کو ہوگی.چونکہ سورۃ ماعون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری زمانہ کے ساتھ متعلق ہے جبکہ اس کی حالت خراب ہوجانی تھی اور آپ کی امّت کے ایک حصہ نے ریا کی نمازیں پڑھنے لگ جانا تھا.یعنی نمازوں کا مغز جاتے رہنا تھا اور آپ کی امت نے دیگر خرابیوں کا شکار ہوجانا تھا اس لئے اب سورۂ کوثر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ابتدائی زمانہ کا ذکر ہے.سورۂ کوثر کے بعد صرف چھ چھوٹی چھوٹی سورتیں باقی رہ جاتی ہیں.میرے نزدیک چونکہ اب قرآن کریم کا خاتمہ نزدیک آگیا ہے اس لئے جیسا کہ سمجھ دار مصنّفوں کا قاعدہ ہے کہ وہ کتاب کے آخر میں آکر مضمون کو سمیٹتے ہیں کبھی خلاصہ بیان کرتے ہیں اور کبھی مضمون کے مغز کو بیان کرتے ہیں تا وہ قارئین پر اثر ڈال سکیں.اسی طرح قرآن کریم اب خاتمہ کے قریب آپہنچا ہے.اس سورۃ کے بعد صرف چھ سورتیں باقی رہ جاتی ہیں.اس لئے اللہ تعالیٰ
Page 8
نے مضمون سمیٹنے شروع کر دیئے ہیں.( میں نے پہلے لکھا ہے کہ یہ سورۃ زمانۂ نبوت کے ابتدا میں نازل ہوئی تھی مگر اب میں نے لکھا ہے کہ اس سورۃ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اب قرآن کریم ختم ہو رہا ہے.بظاہر اس میں اختلاف نظر آتا ہے مگر در اصل اختلاف نہیں.میں پہلے سیپارہ کی تفسیر میں اس امر کو ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی دو ترتیبیں ہیں.ایک ترتیب زمانۂ نزول کے ابتدائی دور کے لحاظ سے ہے اور دوسری اسلام کی عمر یعنی زمانۂ قیامت تک کے حالات کے لحاظ سے ہے اور وہی اصلی ترتیب ہے.قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ دونوں زمانوں کی ترتیب اس کی بلیغ حکمتیں رکھتی ہے.پس گویہ سورۃ ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی تھی مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ دوسری ترتیب میں اسے قرآن کریم کے آخر میں رکھاجائے گا اس لئے اس کا مضمون اس طرح نازل کیا گیا کہ وہ قرآن کریم کے آخر میں رکھا جاکر قرآنی ترتیب کی شان کو ظاہر کرے.چنانچہ اس کا مضمون باوجود اس کے کہ یہ سورۃ ابتدا میں نازل ہوئی تھی بعد میں نازل ہو نے والی سورتوں کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے کہ گویا یہ سورۃ ان بعد میں نازل ہو نے والی سورتوں کے بعد میں نازل ہوئی ہے ) اور سورۃ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اب ختم ہو نے والا ہے.سارے مضامین اس میں آ گئے ہیں.سب مطالب اس میں بیان کر دیئے گئے ہیں.او رتمام قسم کی خوبیاں اور اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں اس لئے اس سورۃ کو اگر کوثر کہہ دیں تو بے جا نہ ہوگا.سورۃ کوثر میں درحقیقت قرآن کریم کا نام بتایا گیا ہے اور یہ مضمون لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے کہ جب شروع میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا اور قرآن کریم کی ابھی چند چھوٹی چھوٹی سورتیں نازل ہوئی تھیں اس وقت جب یہ کہا جاتا تھا کہ اس کتاب میں سب معارف پائے جاتےہیں، سب مضمون پائے جاتے ہیں اور یہ انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے تو تم کہا کرتے تھے اس میں ہے کیا چند اخلاقی باتیں بیان کی گئی ہیں.اب اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ ابتدا میں تو یہ کتاب تمہارے نزدیک چند اخلاقی باتوں کا مجموعہ تھی لیکن اب جبکہ یہ کتاب ختم ہو رہی ہے.بولو! کیا یہ چند اخلاقی باتیں ہیں.کیا اس میں تمام معارف اور مطالب بیان نہیں کئے گئے.کیا اس میں سارے مضامین نہیں آگئے.کیا یہ انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والی نہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے خاتمہ پر اس کے نزول کے مقصد کے تمام و کمال طور پر پورا ہو جانے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے اور بتا یا ہے کہ جو دعویٰ ابتداء اسلام میں کیا گیا تھا اب وہ قرآن کریم کے مکمل ہونے سے لفظاً لفظاً پورا ہو گیا ہے.پھر اس سورۃ میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی تمام علوم کے جامع ہیں گویا اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 9
نے بھی اپنی عمر گذار لی ہے اور قرآ ن کریم کا نزول بھی ختم ہو رہا ہے یعنی آپؐبھی عمر کے خاتمہ پر ہیں اور قرآن کریم بھی خاتمہ پر ہے.اب تم دیکھو کیا قرآن کریم اپنے اندر غیر معمولی وسعتِ مضامین رکھتا ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم خیال کرتے تھے کہ یہ ابتر ہیں.اب دیکھو کیا آپ کے وجود نے اپنے آپ کو پھیلایا ہے یا نہیںاور جہاں تک آپؐکے اخلاق فاضلہ کا تعلق ہے آپؐنے ان کے اندر کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں.اب بتاؤ کہ آپؐکو کوثر مل گیا یا نہیں ملا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتا سکتی ہیں آپ کے اخلاق کیسے تھے؟تو حضرت عائشہؓ نے جواب میں فرمایا کَانَ خُلُقُہُ کُلُّہُ الْقُرْاٰنُ (الطبقات الکبرٰی لابن سعد ذکر صفۃ اخلاق رسول اللہ ) کہ مجھے آپؐکے اخلاق بتانے کی کیا ضرورت ہے قرآن کریم پڑھو اس سے تمہیں آپؐکے اخلاق کا پتہ لگ جائے گا.قرآن کریم نے جہاں حکم دیا ہے کہ یوں کرنا چاہیے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور قرآن کریم نے جس امر سے منع کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں کیا کرتے تھے قرآن کریم پڑھو اسی سے آپ کے اخلاق کا پتہ لگ جائے گا.قرآن کریم اگر کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو تو سمجھ لو کہ آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے.قرآن کریم اگر کہتا ہے کہ روزے رکھو تو سمجھ لو کہ آپ روزے رکھا کرتے تھے قرآن کریم اگرصدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ صدقہ و خیرات دیاکرتا کرتے تھے.قرآن کریم اگر نرمی کا حکم دیتا ہے تو سمجھ لو کہ آپ نرمی کیا کرتے تھے.قرآن کریم اگر حکم دیتا ہے کہ مجرم کو ایسی سزا دو جس سے اس کی اصلاح ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ مجرم کو سزا اسی شکل میں دیا کرتے تھےکہ اس کی اصلاح ہو جائے.قرآن کریم اگر حکم دیتا ہے کہ قصوروں کو معاف کردو توسمجھ لو کہ آپ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرتے تھے.آپ کی تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے سوانح بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی سیرت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.قرآن کریم آپ کی مکمل تصویر ہے.گویا قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو موتی ہیں جو ایک ہی سیپ سے توأم نکلے ہیں جیسے توأم بچے ہوتے ہیں ان کی شکلیں ایک جیسی ہو نے کی وجہ سے بعض دفعہ وہ الگ الگ پہچانے تک نہیں جاتے ان کی پیدائش کے وقت ڈاکٹر ان پر نشان لگا دیتے ہیں تا معلوم ہو کہ کون سا بچہ پہلے پیدا ہوا ہے اور کون سا بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے یہی حال قرآن مجید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.ایک کو دیکھو اور دوسرے کو پہچان لو.اور دوسرے کو دیکھو تو پہلے کو پہچان لو.حضرت عائشہؓ کے قول کے بھی یہی معنے ہیں کہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا جڑواں بچے ہیں، ایک ہی سیپ کے دو موتی ہیں.قرآن کریم کو دیکھنا ہو تو
Page 10
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم کو دیکھ لو.جو باتیں اس میں پائی جاتی ہیں وہ سب آپ کے وجود میں پائی جاتی ہیں.اور جوفعل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ قرآن کریم میں پایا جاتا ہے اور جو آپ نہیںکرتے تھے وہ قرآن کریم میں نہیں پایا جاتا.گویا ایک سے دوسرے کو روشنی ملتی ہے.قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو جِلا دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم قرآن کریم کو جِلا دیتے ہیں.عجیب بات یہ ہے کہ سورۂ کوثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ نبوت کے ابتدا میں نازل ہو تی ہے لیکن اس میں آخری زمانہ کی خبر اس تفصیل سے دی گئی ہے کہ انسان محو حیرت ہو جاتا ہے اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی کیا شان ہو گی اور قرآن کریم کی تکمیل کے وقت اس کی کیا شان ہو گی.جب یہ سورۃ آپ کی نبوت کے دوسرے یا تیسرے سال نازل ہوئی تو آپ کی حیثیت کیا تھی.آپ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا.آٹھ دس آدمی آپ پر ایمان لائے تھے.پندرہ بیس چھوٹی چھوٹی سورتیں آپ پر نازل ہوئی تھیں.آپ کے کیریکٹر اور نبوت کے مطابق اخلاق فاضلہ کے مظاہرے کے کوئی مواقع نظر نہیں آتے تھے دوسرے انبیاء علیہم السلام کی وہ پیشگوئیاں جن کے متعلق آپ کہتے تھے کہ وہ آپ کے متعلق ہیں یا وہ پیشگوئیاں جو آپ خود اپنے متعلق کیا کرتے تھے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھیں.آپ کا وجود ایسا تھا جیسے کسی بڑے درخت کی گٹھلی سے صرف ایک کونپل نکلتی ہے.وقت سے پہلےکون کہہ سکتا ہے کہ وہ چھوٹی سی کونپل ایک دن ایک عظیم الشان درخت بنے گی.لوگ اس کے پھل کھائیں گے اس کے سایہ میں بیٹھیں گے اس وقت اسے ایک بکری بھی اپنے پاؤں سے دباسکتی ہے.ایک کیڑا بھی اسے کاٹ کر گرا سکتا ہے.قرآن کریم کی ابھی چند ہی سورتیں نازل ہوئی تھیں اور چند گنتی کے آدمی ہی آپ پر ایمان لائے تھے.اس وقت جب آپ کی کو ئی حیثیت نہیں تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ اے مکہ والو تم یہ خیال نہ کرو کہ قرآن کریم کیا ہےچنداخلاقی باتیں ہیں.ایسا نہیں.یہ تو ایک مکمل کتا ب بننے والی ہے.یہ خیال مت کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیثیت نہیں.وہ تو ایک عظیم الشان مقام پر پہنچنے والے ہیںجسے کوثر کہا جاتا ہے.کوثر کےلفظ میں آپ کی زندگی، آپ کو عطا شدہ علوم، اخلاق فاضلہ اور فتوحات سب شامل ہیں.اس وقت جبکہ آپ کو اور آپ کے پاس بیٹھنے والوں کو لوگ مارتے تھے، پیٹتے تھے.آپ کے اخلاق کی برتری کو کوئی کیا ثابت کر سکتا تھا.اس وقت اگر کوئی کہتا کہ آپ رحیم و کریم ہیں تو دشمن کہہ سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے کمزور ہیں کہ لوگ انہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور مختلف قسم کی ایذائیں دیتے ہیں.جب دشمن زبردست ہے تو پھر معافی
Page 11
دینے اور رحم کرنے کے کیا معنے.جب تک آپ کو وہ مقام حاصل نہ ہوتا کہ آپ غالب ہو تے اور آپ کا دشمن زیر ہو تا اور پھر آپ رحم کرتے.اس وقت آپ کی یہ صفت کیسے ثابت ہو سکتی تھی جب آپ کے سا تھ چند آدمی تھے اور وہ بھی کمزور تھے اور ان کی کوئی پوزیشن نہ تھی.جب وہ اکٹھے ہوکر بیٹھتے تھے تو ان سے کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ جماعت لاکھوں لاکھ کی تعداد تک پہنچ جائے گی.یہ کتنی بڑی خوبی ہے او رکتنا بڑا نشان ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں جب آپ کے اخلاق اور آپ کی کتاب کے مکمل ہو نے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکتا تھا اس وقت یہ کہہ دیا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ ماننا پڑے گاکہ قرآن کریم بھی کوثر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بھی کوثر ہیں.دعویٰءنبوت کے ابتدا میں آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا سلوک کیا تھا.صرف چند وحیاں تھیں چند وعدے تھے.اس وقت یہ کہنا کہ دیکھو خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عظیم الشان سلوک کرتا ہےکہاں تک لوگوں کو یقین دلا سکتا تھا اور اس پر کون اعتبار کر سکتا تھا.آپ کا وجود اس صورت میں اسی وقت پیش کیا جا سکتا تھاجب ساتھ یہ بھی بتایا جاتا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی کیا کیا مدد اور نصرت فرمائی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیسا ہے کیا بلحاظ کلام کے اور کیا بلحاظ آپ کے ذاتی جوہر کے.یہ معاملہ دو قسم کا ہو سکتا تھا.(۱) خدا تعالیٰ کا براہ راست معاملہ (۲) بندوں کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کا معاملہ.یہ سب باتیں جب تک ظاہر نہ ہو تیں اس دعویٰ کی اہمیت ظاہر نہیں ہو سکتی تھی.خدا تعالیٰ نے ابتدائی زمانہ میں ہی آپ سے یہ کہہ دیا کہ ساری کی ساری بہترین اور بے حساب چیزیں آپ کو ملیں گی.ہر امرمیں آپ کو کوثر ملے گا.آپ کی خوبیاں جگمگاتی چلی جائیں گی.اللہ تعالیٰ بے انتہا کرم کا مظاہرہ کرے گااور آپ کو ایسی کتاب ملے گی جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکے گی.یہ سب باتیں آپ کی زندگی میں ہی آپ کی ذات میں پو ری ہوئیں اور دوست و دشمن نے اس کی گواہی دی.یہ اپنی ذات میں کتنا بڑا معجزہ ہے.اللہ تعالیٰ کے انبیاء جب دنیا میں آتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ فاتح رہے گا.چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں فاتح رہوں گا.حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں فاتح رہوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں اپنے دشمنوں پر فتح پاؤں گا.اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ اپنے دشمنوں پر فتح پائیں گے.یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی اس کے مامور آتے ہیں وہ اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کفار مکہ اور عرب والوں پر غالب آجاؤں گا بلکہ آپ نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت زیادہ غالب رہوںگا.میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت بھی زیادہ غالب رہوں گا.میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
Page 12
نسبت بھی زیادہ غالب رہوں گا.اگر آپ فرماتے کہ میں غالب آجاؤں گا تو اس کے صرف یہ معنے تھے کہ میں اپنے دشمنوں پر غالب آجاؤں گا.ایسا ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آئے.جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام غالب آئے.جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غالب آئے یا دوسرے تمام انبیا ء غالب آئے.لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اس سے بڑھ کر دعویٰ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں پر ہی غالب نہیں کرے گا بلکہ آپ کو وہ غلبہ ملے گا جس کی نظیر نہیںملتی.وہ صرف غلبہ نہیں کہلائے گا وہ کوثر کہلائے گا.آپ کو ایک کتاب ہی نہ ملے گی بلکہ ایسی کتاب ملے گی جو غیر محدود مطالب پر حاوی ہو گی.آپ کے اخلاق دوسرے انبیاء سے بھی اعلیٰ اور بلند پایہ ہوں گے.خدا تعالیٰ کا معاملہ آپ سے غیر محدود ہو گا اور یہ وہ چیز نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی تھی.یہ وہ چیز نہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی تھی.یہ وہ چیز نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دوسرے انبیاء میں پائی جاتی تھی.یہ فرق اس لئے تھا کہ آپ کا دعویٰ صر ف نبی ہو نے کا نہیں تھا بلکہ آپ کا دعویٰ خاتم النبییّن ہو نے کا تھا.یہ دعویٰ آپ نے اس وقت کیا جب آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی.آپ کی ذات کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا.آپ کی حیثیت ایک معمولی انسان کی تھی.اس وقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا انجام صرف نبیوں والا نہیں ہو گا بلکہ نبیوں کے سرداروں والا ہوگا.دیکھو یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف دشمن کے مقابلہ میں جیتنے کا سوال نہیں.آپ اس طرح جیتیں گے کہ پہلے انبیاء کی کامیابی کی آپ کے مقابل پر کوئی نسبت نہیں ہوگی.کتنا کھلا چیلنج ہے جوں جوں زمانہ گذرتا گیا اور جوں جوں حالات بدلتے گئے سورۂ کوثر کا ایک ایک مفہوم پورا ہونے لگا.وہ کتا ب جو پہلے چندسورتوں کی نظر آتی تھی جس میں چند علمی اور اخلاقی مضامین بیان کئے گئے تھے اب اس کے اندر تمام دنیا کے علوم آنے لگے اور جب وہ کتاب خاتمہ کو پہنچی تو اس کے مقابلہ میں دوسرے انبیاء کی تمام کتابیں ہیچ رہ گئیں.جب قرآن کریم کا نزول ختم ہوا تو اس نے صرف مکہ والوں کی باتوں کو ہی جھوٹا ثابت نہیں کیا اس نے شعرائے عرب کے کلام کو ہی ہیچ ثابت نہیں کیا بلکہ جب قرآن کریم کانزول ختم ہوا توکیا زبور، کیا تورات، کیا انجیل، کیا وید اور کیا ژند و اوستا سب کتابیں اس کے مقابلہ میں ہیچ رہ گئیں.یاجب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخرکو پہنچےتو اپنے اخلاق کی بلندی اور روحانیت کی شان کے ساتھ ابو جہل اور عاص بن وائل کوہی آپ نے شرمندہ نہیں کیا اور ان پر ہی اپنی برتری کو ثابت نہیں کیا بلکہ آپ کی زندگی کے حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ جو کوثر آپ کو ملا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو بھی نہ مل سکا.آپ کو خدا تعالیٰ کی جو نصرت اور تائید حاصل ہوئی وہ
Page 13
دوسرے انبیاء کو بھی حاصل نہ ہوئی.آپ کی وفات کے وقت ابو جہل اور عاص بن وائل وغیرہ کےمقابلہ میں ہی آپ کو نصرت الٰہی اور تائید غیبی نہیں ملی بلکہ جب آپ کا مشن کمال کو پہنچا تو ابوجہل اور عاص بن وائل وغیرہ تو کیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کی نسبت بھی آپ کو زیادہ نصرت الٰہی اور تائید غیبی مل چکی تھی.ابتدا میں چند آدمی آپ پر ایمان لائے تھے اس وقت خدا تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ میں تیری جماعت میں اتنی برکت دوں گا کہ انسانوں کے لحاظ سے دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی جماعت تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گی.زمانہ ترقی کرتا گیا.اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور عشق پیدا کیا.ایک طرف آپ کا دائرہ وسیع ہو گیا اور دوسری طرف تمام ملک میں آپ کی تعلیم نے وہ اثر کیا کہ آپ کی وفات کے وقت دنیا نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ ابوجہل اور عاص بن وائل کے ساتھیوں کےمقابلہ میں ہی آپ کو اچھے اتباع ملے بلکہ آپ کی وفات کے وقت دنیا نے یہ مان لیا کہ جو اتباع آپ کو ملے ہیں ان کے مقابلہ میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کےساتھی بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے.چنانچہ آپ فرماتے ہیں لَوْکَانَ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی حَیَّیْنِ لَمَا وَسِعَھُمَااِلَّا اتِّبَاعِیْ (الیواقیت والجواہر الجزء الثانی صفحہ ۳۴۲) اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام بھی زندہ ہو تے تو ان کو میرے صحابہ ؓ میں شامل ہوئے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تا.گویا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام بھی آپ کے زمانہ میں زندہ موجود ہوتے تو وہ بھی آپ کے فرمانبردار اور مطیع ہو تے دیکھو کتنا بڑا کوثر ہے جو آپ کو عطا کیا گیا.اگر آپ کی ابتدائی حالت کو دیکھاجائے، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ جو ابتدائی سلوک تھااسے دیکھا جائے،آپ کے اخلاق کے مظاہروں کو دیکھا جائے اور پھر آپ کے آخری انجام کو دیکھا جائے تو دل ایمان سے لبریز ہو جاتا ہے.سورۂ کوثر کا سورۂ ماعون سے دوسرا تعلق دوسرا تعلق سورۂ کوثر کا سورۂ ماعون سے یہ ہے کہ سورۂ ماعون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص تکذیب دین کرتا ہے اس میں چار نقص پیدا ہو جاتے ہیں (ا) بخل جیسے فرمایا فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ.وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ.یعنی وہ یتیم کو دھتکارتا ہے اور مسکین کوکھانا کھلانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا (۲)ترک صلوٰۃ گویا ایک طرف بخل پیدا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو جاتی ہے (۳)کمزوریٔ ایمان پیدا ہوجاتی ہے جس کے نتیجہ میں انسان کے اندر شرک کا مادہ پیدا ہوجاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اوّل تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں اور اگر پڑھتے ہیں تو پوری توجہ سے نہیں پڑھتے.وہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہی خدا ہیں وہ اس لئے نمازیں پڑھتے ہیں تا انسان یہ کہیں کہ فلاں بڑا نمازی ہے.لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں.گویا ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے انکار کرتے ہیں تو
Page 14
دوسری طرف وہ انسان کو الوہیت کے مقام پر لے جاتے ہیں.(۴) آسان ترین نیکیوں سے روکناجیسے فرمایا وَیَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ یعنی ادنیٰ سے ادنیٰ سلوک بھی جو بغیر تکلیف اٹھائے کسی ہمسایہ سے کیا جا سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتے.بخل میں تو یہ تھا کہ وہ کارآمد چیز خرچ نہیں کرتے مگر یہاں بتایا کہ وہ معمولی سے معمولی چیز جس سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا وہ بھی دوسرے کو نہیں دیتے.کسی نے تھوڑی دیر کے لئے ہتھوڑا مانگ لیا تو اس سے دینے والے کا کیا نقصان ہو جاتا ہے یا تھوڑی دیر کے لئے پھونکنی لے لی تو اس سے کیا نقصان ہو جاتا ہے مگر وہ اس کی توفیق نہیں پاتا.یہ چار بدیاں ہیں جو کمزور مسلمانوں اور منافقوں میں پائی جاتیں ہیں اور جنہیں پہلی سورۃ میں بیان کیا گیا ہے.ان کے مقابلہ میں اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مومن کے اندر جس کی بہترین مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چار خوبیاں پائی جاتی ہیں.(۱)کوثر یعنی سخاوت.کوثر کے معنے جہاں زیادہ کے ہوتے ہیں وہاں زیادہ دینے کے بھی ہوتے ہیں.جب آپ کو کوثر ملا تو آپ نے دوسروں کو بھی کوثر دیا.گویا مومن کی پہلی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے.(۲) ترکِ صلوٰۃ کے مقابلہ میں فرمایا.فَصَلِّ.تو نمازوں کی طرف توجہ کر.پہلی سورۃ میں کمزور مسلمانوں اور منافقوں کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پوری توجہ سے نہیں پڑھتے.اس کے مقابلہ میں اس سورۃ میں فرماتا ہے کہ جب کوئی کوثر کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ نمازوں کا پابند ہوجاتا ہے.تیسرے پہلی سورۃ میں بتایا تھا کہ جولوگ کمزور ایمان والے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے اور ریا کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں مگر اس کے مقابلہ میں یہاں فرمایا لِرَبِّکَ یعنی مومن کامل کی نمازیں لوگوں کے لئے نہیں ہوتیں بلکہ اپنے رب کے لئے ہو تی ہیں.چوتھے پہلی سورۃ میں بتایا تھا وَیَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ کہ وہ لوگ اپنے ہمسایہ کو ادنیٰ سے ادنیٰ احسان اور سلوک سے بھی محروم رکھتے ہیں.یہاں فرمایا وَانْحَرْ.اے میرے مومن بندے تو قربانیاں کر اور اپنی قوم کی ہررنگ میں مدد کر.گویا پہلی سورۃ میں چار عیب کمزور مسلمانوں اورمنافقو ں کے بیان کئے تھے اس کے مقابلہ میں اس سورۃ میں مومن کی چار خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور اس طرح قریب کی پہلی سورۃ اور سورۂ کوثر کے مضامین میں ایک لطیف تطابق پیدا کر دیا ہے.سورۂ کوثر کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں فاء لانے کی وجہ سورۃ کوثر کی آیت فَصَلِّ لِرَبِّکَ میں فَصَلِّ پر فاء لائی گئی ہے.اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس بات میں بھی اس سورۃ کو پہلی سورۃ سے مشابہت ہے وہاں بھی فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ فرمایااور یہ نتیجہ تھا پہلی باتوں کا اور یہاں بھی فَصَلِّ فرمایا.پس یہاں بھی یہی مراد ہے کہ کوثر ( یعنی جس کا خدا تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو ) کے نتیجہ میں دین میں ترقی کرنے کی تو فیق ملتی ہے جس طرح
Page 15
تکذیبِ دین کے نتیجہ میں انسان نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں )اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کر نے والا(اور)بار بار رحم کرنے والا ہے( شروع کرتا ہوں ) اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَؕ۰۰۲ (اے نبی )یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے.حلّ لُغات.اَلْكَوْثَرُ.اَلْكَوْثَرُکے معنے ہیں(۱) اَلْکَثِیْرُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ.ہر چیز کاکسی کے پاس کثرت سے پایاجانا (۲) السَّیِّدُ الْکَثِیْـرُ الْـخَیْـرِ.قوم کا سردار جس کے اندر بڑی خیر اور برکت پائی جاتی ہو.(۳)اَلرَّجُلُ الْکَثِیْـرُ الْعَطَاءِ وَالْـخَیْـرِ.ایسا انسان جو بڑا سخی ہو اور دنیا میں بڑی کثرت سے نیکیاں پھیلانے والا ہو.(۴) نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ.کوثر ایک نہرکا بھی نام ہے جو جنت میں پائی جاتی ہے.(اقرب) اَلْکَوْثَر کے لغوی معنے نہر کے نہیں اقرب الموارد کے مؤلف نے جو کوثر کے ایک معنے نَـھْرٌ فِی الْجَنَّۃِ کے کئے ہیں یہ معنے لغت کے نہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لفظ ِ کوثر عرب میں استعمال ہوتا تھا اس کے یہ معنے سمجھے جاتے تھے.بلکہ جب کوثر کالفظ قرآن کریم اور احادیث میں استعمال ہوا اور مسلمانوں نے بتایا کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گی تو عرب میں یہ معنے بھی رائج ہو گئے اور لغت والوں نے مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق ان معنوں کو بھی کتب لغت میں درج کردیا.ورنہ اس لفظ کے اصل معنے وہی تین۳ ہیں جو اوپر درج کئے گئےہیں.کوثر کے معنے نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃ کے کرنے کی بنیاد کوثر کے ان معنوں کی بنیاد کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعض احادیث پر ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہیں چنانچہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اَتَيْتُ عَلٰى نَـهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُوءِ الْمُـجَوَّفِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ (بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ) یعنی میں ارتقا ء کرتے کرتے جنت میں ایک مقام پر پہنچا جہاں مجھے ایک نہر نظر آئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے بنے ہوئے گنبدوں کی مانند تھے میں نے جبریل سے
Page 16
پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ جبریل نے کہا یہ کوثر ہے.یہ حدیث مسلم میں بھی آتی ہے مگر حدیث کے وہ الفاظ جو میں نے اوپر درج کئے ہیں بخاری کے ہیں.ابن جریر تابعی جو ایک مشہور مفسر گذرے ہیں اور جنہوں نے جامع البیان کے نام سے تیس جلدوں میں تفسیر لکھی ہے وہ حضرت انس سے روایت درج کرتے ہیں کہ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَوْثَرِ فَقَالَ هُوَ نَـهْرٌ أَعْطَانِيْهِ اللّهُ فِي الْـجَنَّةِ تُرَابُہٗ مِسْکٌ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلٰی مِنَ الْعَسَلِ تَرِدُہُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ اَعْنَاقِ الْـجُزُرِ.قَالَ اَبُوْ بَکْرٍيَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّـهَا لَنَاعِـمَةٌ قَالَ اٰكِلُهَا أَنْعَمُ مِنْـهَا (ابن جریر تفسیر سورۃالکوثر )یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس کی مٹی مشک کی طرح ہے اور پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اس پر ایسے پرندے آتے ہیں جن کی گردنیں گاجر کی طرح نرم ہیں حضرت ابوبکرؓنے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ان پرندوں کی گردنیں گاجر کی طرح نرم ہیں تب تو وہ بہت ہی نرم ہوئیں.آپ نے فرمایا جو ان جانوروں کے کھانے والے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ نرم ہیں.امام احمد بن حنبلؒ نے بھی اپنی مسند میں یہی روایت نقل کی ہے لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکرؓ کی بجائے حضرت عمرؓ کا نام لیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا.ایک روایت حضرت عائشہؓ سے بھی آتی ہے بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہؓ سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کوثر ایک نہر ہے جو جنت میں ہو گی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی جائے گی.(بخاری ابواب التفسیر ) کوثر کی آواز سنے جانے کے متعلق حضرت عائشہؓ کی ایک روایت اور اس کے صحیح معنے ایک اور روایت میںحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص کوثر کی آواز سننا چاہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لے تو اسے کوثر کی آواز آنے لگ جائے گی.یہ ابوکریب کی روایت ہے جو ایک بہت بڑے محدث گذرے ہیں (ابن جریر تفسیر سورۃ الکوثر ) عام طور پر لوگ اس کے یہ معنے سمجھتے ہیں کہ کانوںمیں انگلیاں ڈالنے سے جو شوںشوں کی آواز آتی ہے وہی کوثر کی آواز ہے.لیکن یہ معنے عقل کے بالکل خلاف ہیں.اس لئے کہ وہ آواز کان کے اندر سے پیدا ہو تی ہےکسی بیرونی چیز کا اس میں دخل نہیں ہوتا اور کوثر کی آواز ایک بیرونی چیز ہے.پس یہ معنے تو قطعی طور پر جاہلانہ ہیں اور کوئی شخص جو ذرا بھی عقل و فہم رکھتا ہوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ان کو منسوب
Page 17
نہیں کر سکتا.خود شُرّاح ان معنوں سے گھبرا گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے جو شوں شوں کی آواز آتی ہے وہ کوثر کی آواز ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کان کی آواز کوثر کی آواز سے مشابہ ہے ( ابن کثیر تفسیر سورۃ الکوثر) میرے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بالکل صحیح ہے مگر جس نے اس کے یہ معنے کئے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے جو شوں شوں کی ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے وہ کوثر کی آواز ہے اس نے احمقانہ معنے کئے ہیں اور وہ اپنی جہالت کا آپ ذمہ وار ہے.نہ حضرت عائشہؓ نے اس کے یہ معنے کئے ہیں اور نہ شرّاحِ حدیث نے اس کے یہ معنے کئے ہیں.بلکہ میرے نزدیک جو معنے شرّاحِ حدیث نے کئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں.آخر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضرت عائشہؓ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے اور نہ معراج میں حضرت عائشہؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں کہ انہوں نے کوثر کو دیکھا ہو اور اس کی آواز کو سنا ہو اس وقت تو آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی.جب معراج میں آپ اکیلے ہی تشریف لے گئے تھے اور آپ نے ہی کوثر کو دیکھا اور اس کی آواز کو سنا تو پھر آپؐہی بتا سکتے تھے کہ کوثر کی آواز کیسی ہے.پھر اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کوثر کی آواز ایسی ہے تب بھی کوئی بات تھی.مگر حضرت عائشہ ؓ نے اس قسم کا بھی کوئی فقرہ استعمال نہیں کیا.پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوثر ایک نہر ہے تو اس کی آواز کوئی نئی قسم کی نہیں ہو سکتی بہر حال جیسے دنیا کی تمام نہروں کی آواز ہو تی ہے ویسے ہی کوثر کی آواز ہو گی.اس کے لئے کانوں میں انگلیاں ڈال لینا اپنے اندر کوئی معقولیت نہیں رکھتا.حقیقت یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ استعارہ میں بات کرتا ہے اور سننے والے اس کے کچھ اور معنے کر لیتے ہیں.مجھے یاد ہے ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے ایام میں مَیں نماز پڑھا کر گھر جا رہا تھا کہ ہجوم میں سے کسی شخص نے مجھے انگور دیئے.مجھے اس وقت معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس شخص نے دیئے ہیں.انگور بہت میٹھے تھے مگر چونکہ دینے والے کو میں نے دیکھا نہیں تھا میں نے گھر آکر کہہ دیا کہ یہ انگور مجھے کوئی فرشتہ دے گیا ہے.میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں مگر لوگوں میں یہ روایت چل پڑی کہ مجھے واقعہ میں کوئی فرشتہ انگور دے گیا ہے اور بعض دوستوں نے تو مجھے پیغام بھیجنے شروع کر دیئے کہ اگر وہ انگور آپ کے پاس ہوں تو ہمیں بھی بطور تبرک کچھ بھجوا دیں.میں نے دوستوں کو بتایا کہ انگور تو مجھے کسی آدمی نے دیئے تھے لیکن ہجوم میں مجھے پتہ نہیں لگ سکا تھا کہ وہ کون ہے اس لئے میں نے کہہ دیا کہ فرشتے نے دیئے ہیں ورنہ دینے والا ایک انسان تھا کوئی فرشتہ نہیں تھا.اسی طرح یہاں بھی استعارہ
Page 18
میں کلام کیا گیا ہے.حضرت عائشہ ؓ سے کسی شخص نے اپنی حماقت سے سوال کر دیا کہ کوثر کی آواز کیسی ہے.آپ نے اسے استعارہ میں جواب دیا کہ تم اپنے کانوں میں انگلیا ں ڈال لو تمہیں کوثر کی آواز آنے لگ جائے گی.آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان دنیا سے اپنے کان بند کر کے دل کی آواز سنتا ہے یعنی فطرت صحیحہ یا اسلام کی آواز کو سنتا ہے تو وہ کوثر کی آواز کو سن لیتا ہے.یعنی کوثر تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے.مگر سننے والوں نے اس کا یہ مطلب لے لیا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لو تو اس کے نتیجہ میں جو شوں شوں کی آواز پیدا ہو گی وہ کوثر کی آواز ہے.احادیث میں کوثر کے معنے جو نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کےکئےگئے ہیں یہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس لئے ان کا انکار نہیںکیا جاسکتا گو زیادہ تر روایات حضرت انس بن مالکؓ سےآتی ہیں لیکن بعض احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہیں.بہرحال یہ احادیث صحیح ہیں.مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ (ا) اس سورۃ میں اسی کوثر کا ذکر ہے جس کے معنے نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا چیز ہے آپ نے فرمایا میں معراج کی رات ارتقاء کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچا وہاں میں نے ایک نہر دیکھی میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ کوثر ہے.اس جواب سے یہ کیونکر نتیجہ نکل آیا کہ یہ وہی کوثر ہے جس کا سورۃ الکوثر میں ذکر آتا ہے جب کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ سورۃ اور وقت میں نازل ہوئی ہے اور معراج اور وقت میں ہوا ہے.یہ سورۃ بھی مکی ہے اور معراج بھی مکی ہے مگر یہ سورۃ معراج سے چھ سات سال پہلے کی نازل شدہ ہے.دو ملتی جلتی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک کے ذکر سے دوسری چیز کا خیال کر لینا تو طبعی بات ہے مگر اس پر حصر کر لینا خلاف عقل ہے ہمارے ہاں ایک استانی تھیں جو بہت ہی مخلص عورت تھیں.ان کے دماغ میں کچھ نقص پیدا ہو گیا تھا.ایک دن وہ ہمارے گھر میں بیٹھی تھیں کہ زلزلہ آیا.ہماری نانی امّاں، وہ مجنون استانی اور دو اور عورتیں چار پائی پر بیٹھی تھیں.نانی امّاں مرحومہ نے فرمایا زلزلہ آیا ہے اس پر وہ استانی کہنے لگیں آپ اطمینان سے بیٹھی رہیں زلزلہ کوئی نہیں آیا صرف میرا سر چکرایاہے.اب دیکھو اگر اس عورت کا سر کبھی کبھی چکراتا تھا تو اس کے یہ معنے تو نہیں تھے کہ اگر زلزلہ کی وجہ سے چارپائی ہلی ہے تب بھی اس کا سر چکرایا ہے چارپائی نہیں ہلی.یہاں بھی بالکل ویسی ہی بات ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کی مٹی مشک جیسی ہے.پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کا نام کوثر ہے لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ سورۂ کوثر میں بھی اسی کا ذکر آتا ہے حالانکہ سورۂ کوثر والی کوثر اور چیز ہے اور جنت والی کوثر اور.سورۂ کوثر کی کوثر کو جنت والی کوثر سے محدود نہیں کیا جا سکتا.غر ض اگر یہ تسلیم بھی کیا جائے کہ اس سورۃ میں بھی اسی نہر کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت
Page 19
میں عطا ہو گی تو پھر یہ معنے بطور حصر کے نہیں ہوں گے.یعنی اس کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ اس جگہ کوثر سے صرف وہی نہر مراد ہے بلکہ مراد یہ ہو گی کہ کوثر مذکور فی القرآن کی ایک آئندہ زندگی کی مثال وہ نہر ہے جو جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی.جنت کی نعما ءکے متعلق قرآن کریم نے یہ اصل بیان فرمایا ہے کہ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا١ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ١ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا (البقرۃ:۲۶)یعنی جب کبھی جنتیوں کو جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل کھلایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتا رہا ہے اور وہاں انہیں ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی.یہ آیت سورۂ بقرہ کی ہے.اس کے بعد سورۂ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ (السجدۃ:۱۸) یعنی جنت میں جو چیزیں مومنوں کے لئے مخفی رکھی گئی ہیں اور جن سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی انہیں کوئی بھی نہیں جانتا.اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جنت کی نعماء کا کسی کو علم نہیں اور دوسری طرف مومنوں کا ان چیزوں کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے بھی دنیا میں ملتی رہی ہیں بظاہر بڑی تذلیل کا فقرہ ہے.اگر کوئی شخص اپنے دوست سے ملنے کے لئے جائے اور وہ دوست اسے یہ کہے کہ ہم تمہیں ایسا پھل کھلائیں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا تو اس پھل کو دیکھ کر بڑی اجڈ طبیعت والا ہی کوئی انسان ہو گا جو یہ کہے کہ یہ پھل میں نے پہلے بھی کھایا ہوا ہے.عام حالات میں ایسا انسان جو سلجھے ہوئے اخلاق رکھتا ہو اس قسم کا فقرہ استعمال نہیں کر سکتا کہ یہ پھل میں نے پہلےبھی کھایا ہوا ہے.بلکہ وہ یہی کہےگا کہ یہ پھل نہایت لذیذ اور عمدہ ہے اگر انسان اپنے ایک معمولی دوست سے بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا تو خدا تعالیٰ کے متعلق یہ بات کیسے کہی جاسکتی ہے.خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگلے جہان میں تمہیں وہ پھل دیئے جائیں گے جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے.ایسے پھلوں کو دیکھ کر مومنوں کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ پھل پہلے بھی کھائےہوئے ہیں بالکل جھوٹ بن جاتا ہے اور چونکہ کوئی جنتی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جو جھوٹ ہو.اس لئے معلوم ہوا کہ اس آیت کے وہ معنے نہیں جو عام طور پر کئے جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا کہ وہ چیزیں جو مومنوں کو جنت میں ملیں گی دنیا کی چیزوں کے مشابہ ہوں گی.گویا ایک طرف ان کو آپس میں متشابہ قرار دیا اور دوسری طرف ان کو بالکل مختلف قرار دیا.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ اس جگہ مادی نعماء اور پھل مراد نہیں بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو روحانی نعمتیں انہیں ملی تھیں وہی متشکل ہو کر انہیں اگلے جہان میں پھلوں اور باغات کی صورت میں مل جائیں گی.جب ایک مومن جنت میں انگور کھائے گا تو وہ کہے گا یہ تو وہ انگور ہیں جو ہمیں دنیا میں دیئے گئے تھے یعنی جو مزہ ہمیں نمازوںمیں آتا تھا
Page 20
وہی ان انگوروں کا ہے.جو مزہ روزوں کا ہمیں دنیا میں آتا تھا وہی مثلاً اس سردے کا ہے.گویا دنیا میں جو عبادتیں کسی نے کی ہوں گی وہی متشکل ہو کر اگلے جہاں میں اس کے سامنے آجائیں گی.احادیث میں ہمیں اس کی بعض مثالیں بھی ملتی ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا کہ میں جنت میں گیا ہوں.جب میں وہاں گیا تو ایک فرشتہ جنت کے انگوروں کے دو خوشے میرے پاس لایا اور ان میں سے ایک مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ آپ کے لئے ہے میں نے اس سے پوچھا کہ دوسرا خوشہ کس کے لئے ہے؟ اس فرشتے نے جواب دیا یہ ابو جہل کے لئے ہے.آپ فرماتے ہیں یہ سن کر میں اتنا گھبرایا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا رسول اور اس کا دشمن دونوں ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کےرسول کے لئے بھی جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ آیا اور اس کے دشمن کے لئے بھی جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ آیا.بدر میںابو جہل کے مارے جانے کے بعد جب فتح مکہ ہوئی تو عکرمہؓ نے جو ابو جہل کا بیٹا تھا غصہ کے مارے وہاں رہنا پسند نہ کیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا.اس کی بیوی اسے لانے کے لئے گئی اور اسے کہا تم بے وقوفی کر رہے ہو جو اپنا وطن چھوڑ کر جارہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے انسان ہیں.انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے.ایسا اچھا سلوک خدا تعالیٰ کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم واپس مکہ چلو تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے.اور تمہارے دین میں بھی کوئی دخل نہیں دیں گے.عکرمہؓ کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ ایک ایسے شخص کو جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سےاتنی دشمنی ہے کہ اس نے آپ کی وجہ سے مکہ میں رہنا بھی پسند نہیں کیا آپ معاف فرما دیں گے بلکہ اس کے دین میں بھی کوئی دخل نہیں دیں گے.مگر بیوی نے اسے یقین دلایا اور وہ اس کے کہنے پر واپس آیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی کہتی ہے آپ نے میرے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر میں مکہ میں ہی رہوں تو آپ میرے دین میں کوئی دخل نہیں دیں گے اور مجھے معاف فرما دیں گے.کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جوکچھ تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ درست ہے.یہ بات عکرمہؓ کی امیدوں کے بالکل خلاف تھی.وہ سمجھتا تھا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے دشمن کو معاف کر دیں جس نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ہر قسم کا دکھ دیا اور آپ کے ماننے والوں کا خون بہایا اور پھر فتح مکہ کے بعد وہ یہ بھی برداشت نہ کر سکا کہ وہ مکہ میں رہے.عکرمہؓ سمجھتا تھا کہ آپ مجھے کسی طرح معاف نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے آپ کی مخالفت میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھی اور میرے باپ نے بھی آپ کوہر قسم کے دکھ دیئے ہیں جن کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی.مگر جب آپ نے
Page 21
فرمایا کہ جو کچھ تمہاری بیوی نے کہا درست ہے تو اس کا عکرمہؓ پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے کہا اگر آپ نے ایسا کہا ہے تو پھرمیں بھی کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نبی کے سوا اور کوئی شخص ایسا کام نہیںکر سکتا اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں.جب وہ ایمان لایا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے خواب کی تعبیر مجھ پر کھل گئ ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ اس خوشے سے مراد یہ تھی کہ عکرمہ ایمان لے آئے گا(السیرۃ الـحلبیۃ فتح مکہ) گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی انگوروں کا ایک خوشہ دکھائی دیا مگر اس سے مراد ایمان تھا اور آپ کو ابو جہل دکھایا گیامگر اس سے مراد اس کابیٹا تھا اسی طرح ایک دفعہ آپؐنے رؤیا میں دیکھا کہ آپ کو دودھ دیا گیا جسے آپ نے پیٹ بھر کر پیا.پھر حضرت عمر ؓ خواب میں آئے تو انہیں اپنا پس خوردہ دیا.جسے انہوں نے بھی پیا.آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ دودھ سے مراد علم ہے.گویا خواب میں دودھ پینے سے مراد علم دین کا میسر آجاناہوتا ہے.(بخاری کتاب التعبیر باب اللبن) ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ اگلے جہاں کے نعماء کی کیا حقیقت ہے.اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ (السجدۃ:۱۸) کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے لئے اگلے جہان میں کیا کچھ رکھا گیا ہے جس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو گی اور دوسری طرف فرماتا ہے وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا کہ انہیں دنیا میں جو چیزیں ملتی تھیں ان کے مشابہ چیزیں اگلے جہان میں دی جائیں گی.گویا پہلی آیت کی خود ہی تردید کر دی پھر احادیث میں بھی آتا ہےکہ جنت کی نعماء ایسی ہوں گی کہ لَا عَیْنٌ رَّأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَـمِعَتْ وَلَا خَطَرَعَلٰی قَلْبِ بَشَـرٍ (بخاری ابواب التفسیر ) نہ تو کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہے نہ کسی کان نے انہیں سنا ہے اور نہ ہی دل کے کسی گوشہ میں اس کا تصور آسکتا ہے.جب وہ ایسی مخفی چیزیں ہیں تو پھر اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا کےکیا معنے ہوئے؟ اس کے وہی معنے ہیں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے.یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں دنیا کی چیزوں کے مشابہ چیزیں مومنوں کو ملیں گی.بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیامیں جو روحانی نعمتیں انہیں ملتی رہی ہیں وہی اگلے جہان میں مختلف پھلوں کی شکل میں متشکل ہو کر ان کے سامنے آجائیں گی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے رؤیا میں ایمان کو انگور کے خوشہ کی شکل میں دیکھا یا آپ نے روحانی علم کو دودھ کی صورت میں دیکھا.اسی طرح وہاں روحانی انگور کھانے سے ایمان میں ترقی ہو گی( اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانیٔ سلسلۂ احمدیہ نے نہایت لطافت سے اپنی کتاب ’’اسلامی اصول کی فلاسفی‘‘ میں بیان فرمایا ہے فجزاہ اللہ احسن الجزاء) اسی طرح روحانی دودھ پینے سےانتڑیوں میں نفخ پیدا نہیں ہو گا بلکہ علم دین ترقی کرے گا اور روحانیت میں اضافہ ہو گا بہر حال قرآنی آیات بتاتی ہیں کہ اگلے جہان میں انسان کو جو کچھ نعمتیں ملیں گی وہ سب کی سب اس جہان کی روحانی نعماء
Page 22
کا ایک تمثّل ہوں گی.اس حقیقت کو قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بھی واضح کیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ(الرَّحمٰن:۴۷) یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہیں.ایک جنت اسے اس دنیا میں ملے گی اوردوسری جنت اگلے جہان میں ملے گی.یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اگلے جہان میں اسی وقت کوئی چیز مل سکتی ہے جب اس جیسی کوئی چیز اس دنیا میں بھی ملے.پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى (بنی اسـرآءیل:۷۳) جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو گا وہ اگلے جہان میں بھی اندھا ہو گا.اس آیت میں اندھوں سے مراد اگر جسمانی اندھے لئے جائیں تب تو بڑے ظلم کی بات ہےکہ ایک شخص اگر پیدائشی اندھا ہے یا اس دنیا میں کسی بیماری کی وجہ سے ہی اندھا ہوا ہے تو اسے اگلے جہان میں بھی اندھا ہی رکھا جائے یہ معنے ہر گز درست نہیں.اندھے سے مراد اس جگہ روحانی اندھا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں روحانی لحاظ سے اندھے ہیں وہ اگلے جہان میں بھی اندھے ہی اٹھائے جائیں گے.اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں نصیب نہیں ہو گا.اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ ہر وہ چیز جو اگلے جہان میں ملتی ہے اس کا اس جہان میں بھی ملنا ضروری ہے.اس تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے باآسانی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب جنت کی نعما ء اس دنیا کی روحانی نعما ء کی تمثیل ہوں گی تو ضرور ہے کہ کوثر کی بھی کوئی تمثیل ہو جو متشکل ہو کر اگلے جہان میں آپ کو نہر کی شکل میں عطا کی جائے جس طرح اس دنیا کا ایما ن اگلے جہان میںانگور کی شکل میں ملے گا اس دنیا کا روحانی علم جنت میں دودھ کی شکل میں ملے گا.اسی طرح ماننا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہان میں بھی کوئی ایسی ہی چیز ملے گی تبھی تو وہ اگلے جہان میں نہر کی شکل میں متمثل کر کے آپ کو دی جائے گی.پس کوثر کے معنے اگر یہاں نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کےکئے جائیں تو ہمیں ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی کوئی ایسی ہی چیز ملنے والی تھی جو اگلے جہان میں آپ کو نہر کی شکل میں متمثل ہو کر عطا کی جائے گی.بہر حال صرف نہر والے معنوں پر کو ثر کا حصر نہیں کیا جا سکتا.چنانچہ اس کا ثبوت صحابہ ؓ کے خیالات سے بھی ملتا ہے.بخاری میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ سمجھی جاتی ہے حضرت ابن عباس ؓسے ایک روایت آتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں قَـالَ فِی الْـکَـوْثَـرِ ھُـوَ الْــخَـیْــرُ الَّـذِیْ اَعْــطَاہُ اللہُ اِیَّـاہُ (بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ) یعنی کوثر سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں ہیں جو اس دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو دی گئی تھیں.دیکھو حضرت ابن عباس ؓ بھی تسلیم فرماتے ہیں کہ جو معنے میں نے اوپر کئے ہیں وہی درست ہیں.جب دنیا میں آپ کو اس قسم کی کوئی چیز ملے گی تبھی وہ اگلے جہان میں نہر کی شکل میں متمثل ہوکر آپ کو عطا ہو گی.
Page 23
اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ ابو البشر نے ایک دفعہ حضرت سعید بن جبیر سے جو اعلیٰ درجہ کے تابعی اور علمِ حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے کہا کہ فَاِنَّ نَاسًا یَزْعُـمُوْنَ اَنَّہُ نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ.آپ توہمیں سنا رہے ہیں کہ وہ تمام اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ملیں ان کا نام کوثر ہے.لیکن لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے یہ کیا بات ہے؟ سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ اَلنَّـھْرُ الَّذِیْ فِی الْـجَنَّۃِ مِنَ الْـخَیْرِ الَّذِیْ اَعْطَاہُ اللہُ اِیّاہُ (بخاری کتاب التفسیر باب اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ) وہ نہر جو جنت میں آپ کو ملے گی وہ بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے یعنی میںیہ نہیں کہتا کہ جنت کی وہ نہر جو آپ کو ملے گی کوثر نہیں.بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوثر بہت سے ہیں اور یہ نہر بھی ان کا ایک حصہ ہے.یہ روایت بھی میری تفسیر کے مطابق ہے اور بتاتی ہے کہ کوثر کے معنے نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے بے شک کئے جائیں مگر ان معنوں پر حصر نہیںکیا جا سکتا.بلکہ وہ نہر بھی سورۂ کوثر والی کوثر کا ایک حصہ ہے جو تمثیل کے طور پر آپ کو عطا ہو گی.پھر بخاری میں حضرت ابن عباس سے روایت آتی ہے کہ اَلْکَوْثَرُ الْـخَیْرُ الْکَثِیْـرُ کوثر کے معنےخیر کثیر کے ہیں.ابو الفداء ابن کثیر اس پر لکھتے ہیں ھٰذَا التَّفْسِیْـرُ یَعُمُّ النَّـھْرَ وَ غَیْرَہُ.ان معنوںمیں نہر اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی شامل ہیں.لِاَنَّ الْکَوْثَرَ مِنَ الْکَثْرَۃِ وَ ھُوَ الْـخَیْـرُ الْکَثِیْـرُ.کیونکہ کوثر کثرت سے نکلا ہے اور اس کے معنے خیر کثیر کے ہیں.پھر کہتے ہیں وَمِنْ ذٰلِکَ النَّـھْرُ.اس خیر کثیر میں سے ایک جنت والی نہر بھی ہے جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ جنت میں ملے گی کَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ عِکْرَمَۃُ وَ سَعِیْدُ ابْنُ جُبَیْـرٍ وَ مُـجَاھِدٌ وَمُـحَارِبٌ وَالْـحَسَنُ ابْنُ اَبِی الْـحَسَنِ الْبَصَـرِیِّ.جیسے ابن عباس اور عکرمہ ؓ اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور محارب اور حسن بن ابی الحسن بصری نےفرمایا ہے کہ کوثر سے مراد بہت سی بھلائیاں ہیں.حَتّٰی قَالَ الْمُجَاھِدُ ھُوَ الْـخَیْـرُ الْکَثِیْرُ فِی الدُّنَیا وَ الْاٰخِرَۃِ.مجاہد نے تو اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ کوثر کے معنے بہت بڑی بھلائی کے ہیں جو اس دنیا میں بھی آپ کو ملے گی اورآخرت میں بھی آپ کو ملے گی.وَقَالَ عِکْرَمَۃُ ھُوَ النُّبُوَّۃُ وَالْقُرْاٰنُ و ثَوَابُ الْاٰخِرَۃِ( تفسیر ابن کثیر سورۃ الکوثر) اور عکرمہؓ کہتے ہیں کہ کوثر میں نبوت، قرآن کریم اور آخرت کا ثواب بھی شامل ہے.گویا کوثرکے وسیع معنے ہیں اور انہیں محدود کرنا جائز نہیں اور جو معنے میں نے کئے ہیں ان میں میرے ساتھ صحابہ ؓ اور دوسرے تابعین بھی شامل ہیں یا یوں کہو کہ چونکہ انہوں نے وہ معنے پہلے کئے ہیں اس لئے میرے معنے ان کے موافق ہیں.اگرچہ انہوں نے اور رنگ میں نتیجہ نکالا ہے اور میں نے اور رنگ میں.میرے دلائل اور ہیں اور ان کے دلائل اور ہیں میں نے ان دلائل کو ردّ نہیں کیا بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل پیش کئے ہیں.
Page 24
پھر ابن جریر کہتے ہیں کہ عطاء بن سائب سے محارب بن دثار نے پو چھا کہ سعید بن جبیر کا کوثر کے بارہ میں کیا قول ہے.سعید بن جبیر کو احادیث کے بارہ میں بہت ملکہ تھا اس پر عطاء بن سائب نے کہا سعید بن جبیر نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے ھُوَ الْـخَیْـرُ الْکَثِیْـرُ یعنی کوثر وہ اعلیٰ درجہ کی بھلائیاں ہیں جو دنیا میں آپ کو دی گئیں.فَقَالَ صَدَقَ وَاللہِ(جامع البیان سورۃ الکوثر).اس نے کہا انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے اَنَّہُ الْـخَیْرُ الْکَثِیْـرُ کوثر سے مراد خیر کثیر ہی ہے مگر ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ھُوَنَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کوثر جنت میں ایک نہر ہے یہ معنے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے خیر کثیر کے معنوں کے خلاف نہیں بلکہ یہ بھی اس میں شامل ہیں جیسے کوئی کہے فلاں کے پاس بہت مال ہے اور پھر کہےاس کے پاس ایک گھڑی بھی ہے تو یہ بات پہلی بات کے مخالف نہیں ہو گی.کیونکہ گھڑی بھی مال میں شامل ہے.جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں جنت کی وہ نہر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ ملے گی وہ بھی ان معنوں میں جو میں نے کئے ہیں شامل ہے اور یہ بھی ایک کوثر ہے.’’یہ ہے‘ ‘ اور ’’یہی ہے‘‘میں بہت بڑا فرق ہوتاہے.مثلاً ہم کہتے ہیں یہ دینار زید کا ہے.اب اس پر قیاس کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دینار یہی ہے اور کوئی دینار نہیں.اسی طرح وہ نہر جو آپؐکو اس پیشگوئی کے نتیجہ میں ملے گی اس کے علاوہ اور بھی کئی کوثر ہیں جو آپ کو ملے.بہرحال واقعہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے وسیع معنوں کو محدود کر نے کی کوئی وجہ نہیں جبکہ خیر کثیر کے معنے پیش کر دہ روایت کے مخالف بھی نہیں.روایت صرف ایک مثال دیتی ہے اس پر حصر نہیں کر تی.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ اگر کوثر کے معنے صرف نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے نہیں بلکہ اور بھی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معنوں کو بیان کیوں نہیںکیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تفسیر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور نہ ہی سارے معنے ثابت ہیں.آپ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے سات بطن ہیں(بخاری کتاب فضائل القراٰن باب انزل القراٰن علٰی سبعۃ احرف ) اور ہر بطن کے سات معنے ہیں.گویا قرآن کریم کی ہر آیت کے کم ازکم ۴۹ معنے ہو نے چاہئیں.اب کوثر کے ایک معنے تو نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے ہوئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیئے باقی ۴۸ معنےآپ نے کہاں بیان کئے ہیں.جب ایک ہی معنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں تو باقی ۴۸معنوں کی ہمارے لئے گنجائش ہوئی اور اگر ہم صرف ایک بطن تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں تب بھی باقی چھ معنے کہاں ہیں؟رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے سات بطن بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک آپ نے بیان فرما دیا باقی چھ کی ہمارے لئے بہرحال
Page 25
گنجائش ہے.رہا یہ سوال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معنے کیوں بیان کردیئے باقی کیوں بیان نہیں کئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی تدبّر اور استنباط سے کھلتے ہیں.سورۂ آل عمران میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب قرآن کریم کی کسی آیت کا مفہوم معلوم کرنے میں لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں تو جو لوگ راسخ فی العلم ہو تے ہیں وہی ان مشکلات کو حل کرنے میں کامیاب ہو تے ہیں عوام الناس ان کو حل نہیں کر سکتے(آل عمران رکوع ۱) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے معنے غور و فکر اور تدبر سے نکلتے ہیں.مگر اس آیت میں کوثر کے جو معنے تھے ان میں سے ایک معنے ایسے تھے جو غور وفکر اور تدبر سے نہیں نکل سکتے تھے اور وہ جنت والی نہر کے معنے ہیں یہ معنے تو وہی بتا سکتا تھا جس نے جنت جا کر دیکھی ہو یااس بارہ میں اسے وحی ہوئی ہو.باقی سارے معنے غور و فکر سے معلوم ہو سکتے تھے پس جو معنے غور اور تدبّر سے معلوم ہو سکتے تھے ان کے بتانے کی خاص ضرورت نہ تھی.اورجو معنے مخفی واقعات سے تعلق رکھتے تھے صرف ان کےبتانے کی ضرورت تھی.سو وہ آپؐنے بتا دیئے.یہ واضح بات ہے کہ ہم معراج پر نہیں گئے.ہم نے وہ نہر نہیں دیکھی جس کی نسبت آپؐسے کہا گیا کہ آپ کو ملے گی.اس لئے یہ معنے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص نہیں بتا سکتا تھا.اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ میں اَلْکَوْثَر کے معنے صرف نہر کے نہیں ہو سکتے اب میں اس بات کے دلائل پیش کرتا ہوں کہ میرے نزدیک اس جگہ کوثر کے معنے صرف نہر کے نہیں ہو سکتے.اس بارہ میں میری پہلی دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ میں بارہا بتا چکا ہوں قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہو تے ہیں ان کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ جتنے معنے لغت میں کسی لفظ کے ہوں وہ سب کے سب وہاں مراد لئے جاتے ہیں.سوائے اس کے کہ کوئی معنے ایسے ہوں جن کو خدا تعالیٰ نے اس جگہ پر یا قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر رد کر دیا ہو.اگر وہ معنے جو ابن عباسؓ نے کئے ہیں اور سعید بن جبیر جیسے عالم نے کئے ہیں اور حسن بصری جو ایک ولی اللہ تھے انہوں نے کئے ہیں اور مجاہد اور محارب جیسے محدثین نے کئے ہیں اور عکرمہؓ نے کئے ہیں اور میں نے کئے ہیں غلط ہوتے تو خدا تعالیٰ انہیں آیات میں کوئی ایساتوڑرکھ دیتا جس سے وہ معنے باطل ہو جاتے یا کسی اور جگہ پر قرآن کریم میں ان کی تردید کر دیتا.لیکن اس کا ایسا نہ کرنا صاف بتاتا ہے کہ صرف جنت کی نہر والے معنوں پر یہاں حصر نہیں کیا گیا.دوسری دلیل اس بات کی کہ یہاں کوثر کے معنے صرف نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ کے نہیں یہ ہے کہ اس سورۃ میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ کے الفاظ آتے ہیں اور یہ تین باتیں ایسی ہیں جو کوثر کے نتیجہ کے طور پر
Page 26
بتائی گئی ہیں فَصَلِّ میں فاء تعقیب کی ہے جس کے معنے نتیجہ کے ہو تے ہیں جیسے کہتے ہیں تَزَوَّجَ فَوُلِدَ لَہٗ.اس نے شادی کی جس کے نتیجہ میںاس کے ہاں بچہ پیدا ہوا یا ذَھَبْتُ اِلٰی بَیْتِہٖ فَسَأَلْتُہُ میں اس کے گھر گیا تو اس سے میں نے سوال کیا یعنی سوال کرنا گھر جانے کانتیجہ تھا.اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ.فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ.ہم نے تجھے کوثر دیا ہے اس کے نتیجہ کے طور پر تو یہ کام کر.اب یہاں یہ معنے چسپاں ہی نہیں ہو سکتے کہ ہم نے تجھے جنت میں نہر دی ہے اس کے نتیجہ میں تو نماز پڑھ اور قربانی دے.تیرادشمن ابتر ہوجائے گا.یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں نے شادی کی ہے جس کے نتیجہ میں کوئٹہ میں زلزلہ آیا.ہر شخص کہے گا کہ زلزلہ کا شادی کے ساتھ کیا تعلق ہے.یہ تو ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے.اسی طرح نماز، قربانی اور دشمن کا ابتر رہنا نہر کا نتیجہ نہیں ہوسکتا.اگر یہ نہر کا نتیجہ ہوتا تو پھر کوئی روایت ایسی بھی آنی چاہیے تھی کہ فلاں وقت نہر کے بدلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے دو نفل پڑھے یا اونٹ کی قربانی کی یا اس کے نتیجہ میں فلاں دشمن کا بیٹا مر گیا لیکن ایسی کوئی روایت نہیں.ہم یہ معنے تو کر سکتے ہیں کہ ہم نے تجھے خیر کثیر دیا ہے اس لئے تو نماز پڑھ اور قربانی دے اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے عمل سے یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں.لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ کوثر سے یہاں نہر مراد ہے اس کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ فلاں دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے جنت میں نہر ملنے کے شکریہ میں نفل پڑھے یا قربانی دی یا فلاں دشمن کا بیٹا اس کے نتیجہ میں مر گیا اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی.خدا تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اس کے شکریہ میں آپ نماز پڑھیں مگر آپ نے اس شکریہ میں نماز نہیں پڑھی.خدا تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ آپ اس کے شکریہ میں قربانی دیں مگر آپ نے اس کے شکریہ میں قربانی نہیں دی اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے.پھر یہ روایت بھی ہونی چاہیے تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک نہر دی ہےاس کے نتیجہ میں فلاں دشمن کے بیٹے مر جائیں گے اور میرے زندہ رہنے والا بیٹا پید اہو جائے گا.مگر اس قسم کی کوئی روایت نہیں.بہر حال اگر کوثر سے محض نہر مراد لی جائے تو ان تینوں باتوں کا اس کے ساتھ کوئی جوڑنظر نہیں آتا.اگر کہو کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ کا حکم آپ کو اس لئے دیا گیا تھا تاکہ آپ اس نہر کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا اس رنگ میں شکریہ ادا کریں تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی بڑا انعام تھا جس کے لئےرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ کا حکم دیا گیا؟ اس سے بڑا انعام تو قرآن کریم تھا اس سے بڑا انعام تو لِقا الٰہی تھا اس کے حاصل ہو نے پر تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ
Page 27
وَانْحَرْ کاحکم نہ دیا گیا اور نہر ملنے پر یہ حکم دے دیا گیا.کیا یہ بات کسی انسان کی عقل میں آ سکتی ہے؟ آخر خدا تعالیٰ سے مقدّم اور کون سی چیز ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے آپ کا سر حضرت عائشہ ؓکے سینہ پر تھا اور حضرت عائشہ ؓ نے آپ کو سہا را دیا ہوا تھا تاکہ آپ کو سانس کی تکلیف نہ ہو.حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں آپ کی وفات سے پہلے میں یہ خیال کیا کرتی تھی کہ وفات کے وقت جسے زیادہ تکلیف ہو تی ہے وہ بڑا گناہ گار ہو تا ہے.لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کے وقت تکلیف ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو ملامت کی اور میں نے سمجھ لیا کہ اس کا ایمان یا عدمِ ایما ن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں (بخاری کتاب المغازی باب مرض النبیّ ).بہر حال حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ت کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا اِلَی الرَّفِیْقِ الْاعْلٰی.اِلَی الرَّفِیْقِ الْاعْلٰی.میں خدا کے پاس جا رہا ہوں، میں خدا کے پاس جا رہا ہوں.اس وقت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اِلَی الْکَوْثَرْ میں کوثر کے پاس جا رہا ہوں.گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بھی جس خواہش کا اظہار فرمایاوہ لِقاءِ الٰہی تھی.مگر لِقاءِ الٰہی کی نعمت ملنے پر تو آپ کو صلوٰۃ و نحر کا حکم نہ دیا گیا اور جنت کی نہر ملنے پر یہ حکم دے دیا گیا.کیا اس نہر کوکوئی چھین سکتا تھا کہ اس کے لئے قربانیوں کی ضرورت تھی یا نمازوں اور دعاؤں کی ضرورت تھی.یا کیاجنت کی نہر ان روحانی انعامات سے بڑھ کر تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے کہ اس کے شکریہ میں صلوٰۃ و نحر کا حکم دے دیا گیا؟ آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، آپ کونبوت ملی، آپ کو ختم نبوت ملی، آپ کو تمام نبیوں کی سرداری ملی.یہ بڑے بڑے انعامات تھے جو آپ پر نازل ہوئے.نہر اس کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مگر مفسرین کے خیال کے مطابق آپ کو نفل پڑھنے کا حکم ملا تو ایک نہر کے لئے.حالانکہ شکریہ کے نفل بڑے انعاموں کے لئے پڑھے جاتے ہیں نہ کہ چھوٹے انعاموں کے لئے؟ یہ امور بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ جنت میں ایک نہر ملنے کے نتیجہ کے طور پر تُو نماز پڑھ اور قربانی دے.بلکہ مراد یہ ہے کہ کوثر ملنے کے نتیجہ میں جو مشکلات پید اہو نے والی ہیں ان سے بچنے کے لئے ہم یہ حکم تجھے دیتے ہیں اور در حقیقت اسی کوثر کے راستہ میں روک ہو سکتی تھی جو دنیا سے تعلق رکھتا ہو اور انسان و شیطان اس میں روک بن سکتے ہوں.اُخروی کوثر کے راستہ میں تو نہ انسان روک بن سکتا ہے نہ شیطان اور چونکہ یہ کوثر دنیا سے تعلق رکھتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ پر بڑے بڑے انعامات نازل کرنے والے ہیں.اور جسے بڑے بڑے انعامات ملا کرتے ہیں اس کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے ان انعامات سے محروم کر دیں.دنیا میں کوئی تحصیلدار بن جائے تو لوگ اس پر حسد کرنے لگ جاتے
Page 28
ہیں.ڈپٹی کمشنر بن جائے تو ان کی جان نکل جاتی ہے.لیکن ہم تجھے وہ نعمت دیں گے جو آدمؑ سے لے کر آج تک کسی کو نہیں ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی.تجھ پر دنیا حسد کرے گی اور تیرے راستہ میں بڑی بڑی روکیں پیداکرے گی.لیکن ہم تمہیں اس کا علاج بھی بتادیتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ تو نماز پڑھ اور قربانی دےپھر تو کامیاب رہے گا اسی طرح اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ کا تعلق بھی نہر سے نہیں.اس کا تعلق بھی کسی دنیوی کوثر سے ہی ہوسکتا ہے.کیونکہ اگر کوثر اخروی ہو تو پھر دشمن کے ابتر ہونے کا پتہ بھی اگلے جہان میں ہی لگے گااور کوئی دشمن اس دلیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتاکہ چونکہ اگلے جہان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر ملے گا اس لئے ان کا دشمن وہاں ابتر رہے گا.یہ جملہ صاف بتا تا ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ اس دنیا میں ثابت ہو گا اور چونکہ یہ نتیجہ ہے کوثر ملنے کااس لئے کوثر بھی اسی دنیا میں ملنا چاہیے.ورنہ جو چیز دنیا میں موجود ہی نہیں اس پر ابو جہل کو کس طرح حسد ہو سکتا تھا.اسے اگر آپ کہتے کہ مجھے جنت میں نہر ملے گی تو ابو جہل کہتا میں تو جنت کا قائل ہی نہیں میں نے حسد کیا کرنا ہے.حسد تو انہی انعامات پر ہو سکتا تھا جو آپ کو دنیا میں ملے.سو انہی انعامات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے وہ کچھ دیں گے کہ تیرے دشمن ہر وقت انگاروں پر لوٹتے رہیں گے مگر اس کے ساتھ ہی ہم تجھے اس کا علاج بھی بتا دیتے ہیں جو یہ ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.تو نماز پڑھ اور قربانی دے اس طرح تو دشمنوں کے حسد سے محفوظ رہے گا اور ہمارے فضلوں کے زیر سایہ ترقی کرتا چلا جائے گا.حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر ملا انسان کے لئے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے جس کو خدا تعالیٰ کوثر کہے جو کثیر سے بھی زیادہ ہوتا ہے.تو اس کے اندازہ کی بندے میں طاقت ہی کہاں ہو سکتی ہے.پس کوثر کی تفسیر کرنا انسان کے لئے ناممکن ہے.نہ کوئی کوثر کی تفسیر بیان کرسکتا ہے اور نہ ہی اس کی تفسیر لکھ سکتا ہے یہ تو خدا تعالیٰ ہی بیان کرے تو کرے.لیکن چند مثالیں تقریب مفہوم کے لئے بیان کی جا سکتی ہیںاور انہی کو ذیل میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی.تفسیر.اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَکے جملہ کو اِنَّا کے لفظ سے شروع کرنے کی وجہ اس سورۃ کو اِنَّا کےساتھ شروع کیا گیا ہے جو اِنَّ اور نَا سےبنا ہے.اِنَّ تاکید کے لئے آتاہے اور نَا جمع کا صیغہ ہے.حالانکہ خدا تعالیٰ جو یہ کلام کر رہا ہے واحد ہے.’’نا‘‘کےمعنے ہو تے ہیں ’’ہم‘‘ اور ’’نی‘‘ کے معنے ہیں ’’میں‘‘ پس بظاہر یہاں اِنَّا کی بجائے’’اِنِّیْ‘‘ کہنا چاہیے تھا کیونکہ قرآن کریم جس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ واحد اور لاشریک ہے.مگر بجائے اَنَا یعنی ’’میں‘ ‘کہنے کے اِنَّا کہا گیا ہے یعنی یقیناً ’’ہم نے‘‘ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس میں
Page 29
حکمت یہ ہے کہ جس نعمت کا یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وعدہ کیا گیا تھا وہ بہت بڑی تھی اور انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالت کو دیکھ کر حیران ہو تا تھا کہ کیا یہ چیز آپ کو مل جائے گی اس لئے اِنَّ کے لفظ سے اس وعدہ کے یقینی ہونے پر زور دیا گیا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گمنام فرد تھے، جب دنیا میں آپ کی کوئی حیثیت نہ تھی اور جب آپ کو ماننے والے صرف دس بارہ انسان تھے اس وقت خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے.ایک ایسی بات ہے جو بالکل دور از قیاس معلوم ہو تی تھی.ہر شخص حیران ہوتا تھا کہ کیا وہ چیز جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے انہیں مل جائے گی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اِنَّ کا لفظ استعمال فرما کر اس وعدہ کے یقینی اور قطعی ہونے پر زور دیا.اسی طرح اَعْطَيْنَا جوماضی کا صیغہ ہے یہ بھی تاکید کے لئے ہے کیونکہ ماضی جب مضارع کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی تاکید کے معنے دیتی ہے.جب کوئی چیز آئندہ ملنے والی ہو اور اس کے متعلق کہہ دیا جائے کہ وہ چیز ہم نے دے دی تو اس کا مفہوم یہی ہو تا ہے کہ وہ چیز ہم ضرور دے دیں گے جیسا کہ ہمارے ہاں ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی لڑکی اپنے لڑکے لئے مانگنے آیا ہوں.تو وہ بعض دفعہ تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا میں یہ رشتہ کر دوں گا اور بعض دفعہ کہتا ہے بس میں نے اپنی لڑکی دے دی.شادی تو بعد میں ہو تی ہے مگر الفاظ وہ یہ استعمال کرتا ہے کہ میں نے لڑکی دے دی.جس کے معنے یہ ہو تے ہیں کہ میرا آپ کو رشتہ دینا بالکل قطعی اور یقینی ہے.غرض ماضی کا صیغہ جب مضارع کے معنوں میں استعمال ہو تا ہے تو وہ تاکید کے معنے دیتا ہے.اس سے پہلے اِنَّ کا لفظ بڑھا کر بار بار زور دے دیا ایک طرف ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اس میں تاکید کے معنے پیدا کئے گئے اور دوسری طرف اِنَّ کا لفظ لا کر اس میں تاکید کے معنے پیدا کئے گئے اور اس طرح بتا دیاکہ گو یہ چیز ملنی تو آئندہ زمانہ میں ہے مگر یہ وعدہ ہمارا ایسا یقینی ہے کہ یوں سمجھو کہ ہم وعدہ نہیں کر رہے بلکہ ایک واقعہ شدہ امر کا ذکر رہے ہیں ان دو تاکیدوں کے علاوہ جب ہم اس امر کو دیکھیں کہ جس کی زبان سے یہ وعدہ کروایا گیاہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے تو عبارت میں اور بھی زور پیدا ہو جاتا ہے.کیونکہ خدا تعالیٰ جو بات کہے اسے یقیناً پورا کرسکتا ہے اور یہ عذر بھی نہیں ہوسکتا کہ وعدہ کر نے والے نے وعدہ تو پختہ کیا تھا مگر مجبوریوں کی وجہ سے پورا نہ کر سکا.دوسرا سوال ’’نا‘‘ کے متعلق پیدا ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ یہاں کیوں استعمال فرمایا؟ اس کے متعلق یادرکھنا چاہیے کہ یہاں جمع کا لفظ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ وعدہ اپنے اندر بڑا تنوّع رکھتا ہےاور اس میں خدا تعالیٰ کے ساتھ ملائکہ اور اس کے قوانین قدرت کی مدد کی طرف بھی اشارہ ہے اور قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ
Page 30
جس وعدہ میں خدا تعالیٰ کے فرشتے یا قوانین قدرت بھی شریک ہوں وہاں مضمون کی وسعت پر دلالت کرنے کے لئے وہ جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے.یہ بتا نے کے لئے کہ اس کام کے پور اکرنے کے لئے فرشتوں اور قوانینِ قدرت کو بھی حکم دے دیا گیا ہے اور ہم سب مل کر یہ کام کریں گے.اگر کوئی سوال کرے کہ کیا فرشتوں اور قوانین کی قدرت خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ علیحدہ قسم کی ہے کہ اس کے ساتھ ملنے سے جمع کا لفظ بولا گیا ہے وہ تو خدا تعالیٰ ہی سے طاقت حاصل کرتے ہیں اس لئے ان کے ملنے سے کوئی نئی طاقت تو پیدا نہیں ہو تی پھر جمع کا لفظ کیوںاستعمال ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک خدا تعالیٰ کے نقطۂ نگاہ سے تو کوئی زائد طاقت پیدا نہیں ہو تی.فرشتے اور قوانین قدرت بھی اس کے تابع ہیں اور وہ کوئی کام براہ راست نہیں کر سکتے.فرشتے بھی خدا تعالیٰ نے بنائے ہیں اور قوانین قدرت بھی اسی نے بنائے ہیں.خدا تعالیٰ نے ہی یہ قانون مقرر کیا ہے کہ پانی غرق کرتا ہے یا پانی آگ کو بجھادیتا ہے.خدا تعالیٰ کے ساتھ پانی کے مل جانے سے کوئی نئی طاقت پیدا نہیں ہو تی یا اس نے آگ کے لئے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ جلاتی ہے یا کھانا پکاتی ہےیہ بھی ایک قدرتی چیز ہے خدا تعالیٰ کو اس سے کوئی زائد طاقت حاصل نہیں ہو جاتی.لیکن دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں اور وہ سب قرآن کریم کے مخاطب ہیں.دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن فرشتوں کو نہیں مانتے اور وہ بھی ہیںجو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں اور فرشتوں کو بھی مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول یا فرشتوں کا مؤیّدوجود نہیں مانتے اور وہ بھی ہیںجو نہ خدا تعالیٰ کومانتے ہیں اور نہ فرشتوں کو.ہاں ایک قانون قدرت کو ضرور تسلیم کرتے ہیں.چونکہ اس آیت میں بیان کردہ مضمون پر خاص زور دینا مقصود تھا اس لئے ان سب قسم کے لوگوں کی تسلی کا طریق اختیارکیا گیا.جو لوگ خدا تعالیٰ کومانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر جھوٹ بولنا کوئی معمولی کام نہیں عام شریف آدمی بھی ایسا نہیں کرتا انہیں اس طرف توجہ دلا دی کہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کر اس کی طرف سے یہ دعویٰ کر رہا ہے.جو لوگ خدا تعالیٰ سے زیادہ اخلاقی دلائل کو تسلیم کرتے ہیں ان کو مدّ ِنظر رکھ کر فرشتوں کے وجود کو ساتھ شامل کر لیا کہ نفس لوّامہ اور ناطقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کر رہا ہے اور جو لوگ خدا تعالیٰ اور فرشتوں دونوں کے منکر ہیں ان کے لئے قانون قدرت کو شامل کر لیا گیا کہ قانونِ قدرت بھی اس کی تائید کر رہا ہے کہ یہ شخص بہت کچھ برکتیں پانے والا ہے.پس چونکہ تین گواہوں کو اس وعدہ کے پو را ہونے کی تائید میں پیش کیا گیا تھا.اس لئے بجائے اِنِّیْ یعنی ضرور میں نے کے اِنَّا یعنی ’’ضرور ہم نے‘‘ کے الفاظ استعمال کئے.اس جگہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وعدہ نے تو کسی آئندہ وقت میں پورا ہو نا تھا پھر ان تین گواہوں کے ذکر سے کون سا
Page 31
ایسا مضمون پیدا ہوتا تھا جو ایک منکر کو ایک حدتک امید دلاتا تھا کہ یہ وعدہ آئندہ ضرور پورا ہو گا.سو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے ایک مذہبی آدمی کے لئے تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک شخص جو راستباز ہے دھوکے باز نہیں عقلمند ہے پاگل نہیں.قانع ہے لالچی نہیں کسی غیرمنطقی اور غیر عقلی عقیدہ کا قائل نہیں.اپنے ہوش و حواس میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے.ایک مذہبی آدمی تو ان حالات میں مجرد خدا تعالیٰ کا نام لے کر دعویٰ کرنے کوہی مدعی کی سچائی کی دلیل سمجھتا ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی اور حضرت زید رضوان اللہ علیھم اجمعین نےمجرد یہ دعویٰ سن کر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے آپ کے دعویٰ کو قبول کر لیا اور کوئی مزید دلیل طلب نہیں کی اسی طرح اور کئی لوگوں نے اس دلیل سے فائدہ اٹھایا.ایک اعرابی سلیم الطبع آپ کا دعویٰ سن کر مدینہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یہ فرمائیے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے.آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے.اس جواب کو سن کر وہ آپ پر ایمان لے آیا.پس مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو نے کا یا خدا تعالیٰ کے وعدہ کا ذکرکرے تو ایک مذہبی آدمی کے لئے یہ دلیل ہی کا فی ہو تی ہے اور اس کی فطرت اسے نہیں مان سکتی کہ مذکورہ بالا حالات میں کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے گا یا غلط دعویٰ کرے گا اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی.مگر اس فطرت صحیحہ کےمالک شخص سے اتر کر ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مزید روحانی ثبوت چاہتا ہے.یہ مزید روحانی ثبوت اس طرح پید اہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے تو اس زمانہ کے نیک اور اعلیٰ درجہ کے مانے ہوئے لوگوں میں سے متعددافراد کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے اور وہ اسے قبول کرلیتے ہیں یابعض شواہد سے متاثر ہو کر بعض ایسے لوگ جو پہلے نیکی میںمعروف نہ تھے اسے قبو ل کر لیتے ہیں.لیکن اس کو قبول کرتے ہی ان کی ایسی کایا پلٹ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں چلتے پھرتے فرشتے نظر آنے لگتے ہیںاور عقل سلیم رکھنے والے کو ماننا پڑتا ہے کہ ان کا فرشتہ بن جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ فرشتے ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ملکوتی تأثرات ان پر نازل ہو رہے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی حاصل تھی.ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو پہلے ہی مکہ کے لوگ فرشتہ سمجھتے تھے(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام اسلام ابی بکر الصدیقؓ) مگر بہت سے ایسے لوگ جوبد اعمالیوں اور فتنہ و فساد اور ظلم میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے جب ان کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت گھر کر گئی تو انہوں نے یک دم اپنے حالات کو بدل دیا اور ایک دن میں عابد و زاہد اور متقی اور حلیم اور
Page 32
منکسر المزاج اور رحیم و کریم اور صادق و وفا دار اور خیر خواہ خلائق ہو گئے.یہ امر یقیناً آپ کی صداقت کا ثبوت تھا اور اس امر کی دلیل تھا کہ آپ کے ساتھ ملائکہ کی مدد ہے جو آپ کےساتھیوں پر اپنا اثر ڈال کر ان کو بھی ملائکہ بنا دیتے ہیں.تیسری دلیل جو یہ بیان فرمائی کہ قانونِ قدرت بھی آپ کی مدد کرے گا اس کے اثرات بھی ظاہر تھے.آپ کی تعلیم قانو نِ قدرت کے مطابق تھی اور اس میں وہ ازلی سچائیاں پائی جاتی تھیں جن کو فطرت صحیحہ ماننے سے باز نہیں رہ سکتی.وہم اور ڈھکوسلہ کا نام نہ تھا.ایک طرف خالص منطقی اور دوسری طرف خالص روحانی تعلیم جس نے عقل و روحانیت کے امتزاج سے ایسی چاشنی حاصل کر لی تھی کہ کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے تعصب کی پٹی کو اتار کر رکھتا تھا تو وہ تیر کی طرح اس کے دل میں گھس جاتی تھی اور وہ اس کا شکا ر ہو جاتا تھا اس کی متعدد مثالیں مکہ والوں کے سامنے تھیں.حضرت عمر ؓ آپ کے قتل کے لئے نکلے اور راستہ ہی میں آپ کی صداقت کے خنجر کا شکار ہو گئے اور گناہ گاروں کی طرح گلے میں ندامت کاپٹکا ڈال کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام اسلام عمر بن الخطاب ؓ).پس آئندہ جو ہو نے والا تھا وہ تو جب ظاہر ہو تا لوگ اسے دیکھتے جس وقت یہ سورۃ نازل ہوئی ہے اس وقت بھی اس کا ثبوت مکہ والوں کےسامنے موجود تھا کہ خدا تعالیٰ آپ کے لئے بول رہا ہے اس کے ملائکہ آپ کی مدد پر ہیں اور قانونِ قدرت آپ کی تائید کر رہا ہے.پس فرماتا ہے کہ میں خدا تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں بھی، میرے ملائکہ بھی اور میرا قانون قدرت بھی اس کوکوثر عطا کرنے والے ہیں.تم میری آواز نہیں سنتے تو کیا ملائکہ کی آواز بھی نہیں سنتے.میرے فرشتوں کی آواز نہیں سنتے تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دنیا کے تمام مذاہب اس وقت تَوہم پرستی اور خلافِ عقل عقیدوں میں مبتلا ہیں اور خلافِ فطرت اعمال میں مشغول ہیں مگر اس کے مقابل پر اس شخص کی تعلیم نہ تَوہم اور نہ خلاف عقل عقیدے بیان کرتی ہے اور نہ خلاف فطرت احکام پیش کرتی ہے.پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ اس کے مخالفوں کے گھر ویران ہوجائیں گے.ان کے معبد سر نگوں ہوجائیں گے اور وہ طوعاً یا کرہاً آخر اس کےقدموں پر آگریں گے اور اسی کا زور اور اسی کا غلبہ ہو جائے گا پس یقین کرو کہ میں اور میرے فرشتے اور میرا قانون قدرت ہم سب اس رسول کو کوثر دینے والے ہیں وہ پھیلاؤ، وہ رفعت اور وہ بلندی جو کسی انسان کو نہ کبھی نصیب ہوئی نہ آئندہ ہوگی.دوسراجواب یہ ہے کہ بادشاہ اپنے کلام میں مفرد کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں.اس کے تتبع میں قرآن کریم میں بھی جہاں خدا تعالیٰ کی بادشاہت پر زور دینا مقصود ہو خدا تعالیٰ کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے.بادشاہ جمع کا لفظ اس امر پر دلالت کرنے کے لئے بولتا ہے کہ میں یہ بات کہنے والا اکیلا نہیں تمام میرے ماتحت لوگ وہی کہیں گے جو میںکہوں گا اور وہی کریں گے جو میں کروں گا.انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ بھی لفظ جمع سے کبھی کبھی
Page 33
اپنی نسبت کلام فرماتا ہے.بادشاہوں کے علاوہ مصنفین بھی کبھی ’’ہم‘‘ کا لفظ بولتے ہیں اور ان کا مطلب بھی یہ ہو تا ہے کہ وہ بھی اور ان کے ہم خیال لوگ بھی اس امرکا اظہار کرتے ہیں.پس یہ ایک محاورہ ہے جو دنیا میں عام استعمال ہو تا ہے.حقیقت یہ ہے کہ انسانی دماغ فرد سے جماعت کو قوی سمجھتا ہے.اس لئے جب قدرت پر زور دینا ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے.یہ بتانے کے لئے کہ ہم وجود میں فرد ہیں لیکن طاقت میں جماعتوں سے بھی زیادہ ہیں چونکہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ بہت بڑا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنی شاہانہ حیثیت میں فرماتے ہیں کہ اس وعدہ کے پورا کرنے میں تمام قدرتیں لگ جائیں گی اور یہ بات پو ری ہوکر رہے گی.اب میں بتاتا ہوں کہ کوثر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں.اوپر کی تشریح کے مطابق وہ تمام امور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ سب کے سب کوثر کا حصہ ہیں اور اس لفظ میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ تمام کمالات جو نبوت کا حصہ ہیں یا نبوت سے ان کا گہرا تعلق ہے ان سب میں آپ کو کوثر ملی ہے.اگر کوئی ایک امر مراد ہوتا تو یہ کوئی انعام نہیں تھا.کیونکہ کسی بات میں کسی کا اور کسی بات میں کسی کا بڑھ جانا تو ایک طبعی امر ہے یہ کوثر نہیں کہلاتا.اس طرح تو ہر نبی کو کسی ایک بات میں دوسرے کے مقابلہ میں فضیلت حاصل ہوسکتی ہے اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں رہتی.پس اگر یہاں صرف یہی مراد ہو تا کہ ہم تجھے کسی ایک بات میں فضیلت دے دیں گے.تو یہ کوئی خاص بات نہ ہوتی.ایک گاؤں میں پچاس ساٹھ آدمی اکٹھے رہتے ہیں تو ان میں سے کئی ایک کو دوسروں پر کسی نہ کسی رنگ میں فضیلت حاصل ہو گی.مثلاً اگر وہاں پانچ دس زمیندار ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کی زمین دوسروں سے زیادہ ہو گی اور یہ ایک فضیلت ہے جو اسے دوسرے زمینداروںپر حاصل ہو گی.یاپھر گاؤں میں معمار ہوتا ہے اسے سب زمینداروں پر یہ فضیلت حاصل ہو تی ہے کہ وہ معماری جانتا ہے اور زمیندار معماری نہیں جانتا.پھر نجار کو معمار اور زمیندار دونوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ نجاری جانتا ہے.معمار اور زمیندار نجاری نہیں جانتے.لوہار کو ان تینوں پر فضیلت حاصل ہو تی ہے.اسے لوہار کا کام آتا ہے ان تینوں کو آہن گری نہیں آتی.پھر کوئی سقّہ ہوتا ہے اسے سقّے کا کام آتا ہے جو دوسروں کو نہیں آتا.دھوبی کو اس پر فضیلت حاصل ہو تی ہے کیونکہ وہ دھوبی کا کام جانتا ہے اور سقّہ یہ کام نہیں جانتا.اسی طرح عطار ہے اسے جو فضیلت حاصل ہے وہ معمار کو حاصل نہیں.نہ بڑھئی، لوہار، سقّے اور دھوبی کو حاصل ہے.غرض قریباً ہر انسان دوسرے پر کسی نہ کسی رنگ میں فضیلت رکھتا ہے.کوئی موٹا ہوتا ہے کوئی دبلا ہو تا ہے.کوئی چھوٹے قد کا ہوتا ہے اور کوئی لمبے قد کا ہو تا ہے.کوئی عالم ہو تا ہے اور کوئی جاہل ہو تا ہے.
Page 34
غرض اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی پائی جاتی ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی ایک بات میں بھی فضیلت کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے.مگر ایسا انعام نہیں جو اسے تمام لوگوں پر فوقیت دے دے اور چونکہ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فوقیت کا ذکر ہے جو آپ کو تمام انبیاء پر حاصل ہے لیکن چونکہ اس بات کا معین ذکر یہاں نہیں کیا گیا اس لئے ماننا پڑے گا کہ یہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام کمالات نبوت میں آپ کو کوثر عطا ہوا ہے اور کوئی نبی کسی کمال نبوت میں بھی آپ کا ہم پایہ اور ہم رتبہ نہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُـحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُـحَمَّدٍ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ إِنَّكَ حَـمِيدٌ مَّـجِيدٌ.کوثر کے معنے اَلْـخَیْـرُ الْـکَثِیْـر کے کوثر کے معنے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اَلْـخَیْـرُ الْکَثِیْـر کے ہیں اور اَلْـخَیْـرُ کا لفظ اسم تفضیل یعنی سب سے زیادہ کے معنوں پر دلالت کرتا ہے.پس اس میں دنیوی امور کا ذکر نہیں.کیونکہ دنیوی امور کا کوئی ریکارڈ دنیا میں نہیں جسے دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکے کہ فلاں بڑا ہے یا فلاں.یہ ریکارڈ صرف روحانی اور آسمانی انعامات کا ہی ہے.پس جب مقابلہ کا ذکر ہے تو اس جگہ وہی اشیاء مراد ہیں جن کا مقابلہ کیاجانا ممکن ہے اور وہ امور نبوت اور امور مذہبیہ ہی ہیں.اَلْـخَیْرُ کے معنے اسی طرح اَلْـخَیْـرُ کے معنے ہو تے ہیں وِجْدَانُ الشَّیْءِ بِـجَمِیْعِ کَمَالَاتِہِ اللَّائِقَۃِ(اقرب) کسی چیز کا مع ان تمام کمالات کے ملنا جو اس میں پائے جاتے ہوں اور جن کی وجہ سے اس کا کوئی نام رکھا گیا ہو.گویا خیر ایسی خوبی یا بھلائی کو کہتے ہیں جس میں وہ تمام کمالات پائے جاتے ہوں جن کی وجہ سےاس خوبی کو خوبی کہا جاتا ہے.مثلاً ہم کہیں ہمیں خربوزہ خیر ملا تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ جو جو خوبیاںایک خربوزہ میں پائی جانی چاہئیں وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں اور جب یہ لفظ نبوت کے لئے استعمال ہو گا توا س کا یہ مفہوم ہو گا کہ جو جو کمالات اصطلاحِ نبوت میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے اپنی پوری شان کے ساتھ آپ کے اندر پائے جائیں گے.وَقِیْلَ حُصُوْلُ الشَّیْءِ لِـمَامِنْ شَأْنِہٖ اَنْ یَّکُوْنَ حَاصِلًا لَّہٗ.یعنی بعض آئمہ لغت یہ کہتے ہیں کے خیر کے معنے ہیں کسی چیز کا اس طرح ملنا کہ اس کا ذاتی جوہر تمام و کمال اس میں پایا جائے.گویا اس لفظ میں وسعت اور عظمت دونوں قسم کامفہوم پایا جاتا ہے.پس جب نبوت کے لئے یہ لفظ بولاجائے گاتو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ تمام کمالات جونبوت میں پائے جانے چاہئیں وہ (ا) سارے کے سارے (۲) اور اپنی پو ری شان کے ساتھ آپ کے اندر پائے جائیں گے.اور وہ تمام نقائص جن کی نبوت نفی کرتی ہے وہ آپ میں ہر گز نہ ملیں گے اور چونکہ لفظ کو ثر کے معنوں میں خیر اور کثیر د۲و معنے پائےجاتے ہیںاس لئے کوثر کے معنے یہ ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
Page 35
نبوت اپنے تمام کمالات کے ساتھ ملی اور ہر ہر کمال بہت بہت ملا.دوسرے لفظو ں میں ہم یوں کہیں گے کہ جونبوت آپ کوملی وہ کیفیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھی اور کمّیت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ تھی.گویا جو جو کمالات نبوت آپ کو عطا ہوئے وہ دوسرے نبیوں کے کمالات سے اعلیٰ تھے اور پھر وہ تعداد میں بھی دوسرے نبیوں سے زیادہ تھے.اگر غور کیا جائے تو یہ لفظ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے صحابہؓ ایک کامل اور آخری نبی موعود سمجھتے تھے اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ سورۂ احزاب میں استعمال ہوا ہے جو ہجرت کے چھٹے سال میں نازل ہوئی توتعجب ہو تا ہے کہ اس قدر آخری زمانہ میں جو اظہار ہوا تھا اس کا علم صحابہؓ کو پہلے سےکیوں کر ہو گیا.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کیونکر ہو گیا.اس کا جواب اس سورۃ سے مل جاتا ہے کیونکہ یہ سورۃ دعویٰ کے چوتھے پانچویں سال ہی نازل ہو گئی تھی اور اس میں در حقیقت ختم نبوت کا دعویٰ تھا.یعنی یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے کمالات اعلیٰ شکل میں ملے اور بہت ملے اور جس کو یہ چیز ملی وہ یقیناً سب نبیوں سے افضل تھا اور خاتم النبیین تھا.یہی وجہ ہے کہ جب سورۂ احزاب نازل ہوئی اور آپ کو خاتم النبیین کا لقب دیا گیا تو صحابہ میں اس پر کسی قسم کا کوئی شور نہیں پڑا.ان کے نزدیک یہ کوئی نیالقب نہیں تھا جو آپ کو دیا گیا.اگر یہ نئی بات ہو تی تو اس پر شور پڑ جاتا.مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کوئی شور نہیں پڑا کیونکہ صحابہؓ آپ کو پہلے ہی خاتم النبیین سمجھتے تھے اور آپ کا بھی یہی خیال تھا.اس لئے سورۂ احزاب کے اترنے پر استعجاب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا.حقیقت یہ ہے کہ جب سورۃ کوثر نازل ہوئی تو ا سی وقت سے آپؐاور صحابہؓ سمجھ گئے تھے کہ آپؐخاتم النبیین ہیں اور تمام نبیوں سے افضل ہیں.ان معنوں کے علاوہ لغت میں کوثر کے معنے ایک ایسے سخی وجود کے بھی ہیں جس میں بڑی خیر پائی جائے.ان معنوں کے لحاظ سے اس سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ ہم تجھے ایک خیر کثیر والا سخی وجود دیں گے.دینے سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اتباع میں سے ایک بہت بڑا سخی وجود پیدا ہوگا.ورنہ اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ کہنےکا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا.اب ہم باری باری دونوں معنوں کو لیتے ہیں.آنحضرت صلعم کو نبوت کے کمالات کا اعلیٰ صورت میں ملنا (۱)پہلے معنے یہ تھے کہ نبوت کے کلمات کا اعلیٰ صورت میں ملنا اور بہت ملنا.اس مضمون کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں اور خدا تعالیٰ کے سوا اورکوئی اسے مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتا.لیکن مثال کے طور پر کچھ باتیں بیان کی جاسکتی ہیں.اس بارہ میں ہمیں سب سے پہلےیہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا دعویٰ کیا تھا کیونکہ کسی کی خوبیوں کا پتہ لگانے کے لئے یہ ضروری ہو تا ہے کہ اس کے دعویٰ
Page 36
کا پتہ لگایا جائے.مثلاً اگر ایک شخص ہمارے پاس آکر کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا استاد ہوں.تو ہم دیکھیں گے کہ آیا استاد ہو نے کی سب شرائط اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں.اگر وہ شرطیں دوسروں کی نسبت اس میں زیادہ پائی جاتی ہوں تو ہم مان لیں گے کہ وہ سب سے بڑا استاد ہے.لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سب سے بڑا استاد ہوں اور جب سوال کیا جائے کہ تم میں کون کون سے کمالات پائے جاتے ہیں اور وہ مثلاً کہے کہ میں انڈے زیادہ کھا جاتا ہوں تو ہر شخص اس کو بے وقوف سمجھے گا.یا وہ کہے کہ میں ڈنٹر زیادہ پیلتا ہوں یا بیٹھکیں زیادہ نکالتا ہوں تو سب لوگ اس پر ہنسیں گے.مگر جب وہ کہے کہ میں بڑا پہلوان ہوں اور پھر وہ کہے کہ میں خوراک زیادہ کھاتا ہوں، بوجھ زیادہ اٹھا سکتا ہوں، ڈنٹر زیادہ پیلتا ہوں اور کئی قسم کے جسمانی کرتب دکھا تا ہوں تو ہم کہیں گے ٹھیک کہتا ہے.پھر ہم اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیا تو کینٹ کا فلسفہ جانتا ہے.اگر ہم اس سے پو چھیں گے کہ کیا تو کینٹ کا فلسفہ جانتا ہے؟ تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ میرا فلسفہ سے کیا تعلق ہے میں نے تو پہلوانی کا دعویٰ کیا ہے فلسفہ دانی کا نہیں کیا.آنحضرت کی حضرت موسیٰ سے مماثلت اور آپ کی حضرت موسیٰ پر فضیلت پس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں.تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے اور کون کون شخص آپ کے دعویٰ میں شریک ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا مقابلہ کر کے دیکھیں اور معلوم کریں کہ آیا آپ واقعی سب سے بڑے ہیں یا نہیں.اس نقطہ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تھا تو ہمیں قرآن کریم میں یہ آیت نظر آتی ہے کہ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا١ۙ۬ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَاۤ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (المزّمل:۱۶) یعنی اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجاہے جو تمہارا نگران ہے اور وہ ویسا ہی رسول ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ ( علیہ السلام )کو رسول بنا کر بھیجا تھا.دنیا میں جتنے نبی گذرے ہیں ان میں معروف نبی موسوی سلسلہ کے انبیاء ہی ہیں.حضرت کرشن ؑ اور حضرت رام چندرؑ کی نبوت کو دوسرے مسلمان تو مانتے ہی نہیں ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے پاس ان کی تاریخ محفوظ نہیں.ان کی تعلیمیں کیا تھیں ہمیں ان کی تفصیلات کا کچھ علم نہیں.صرف گیتا ایک ایسی کتاب ہے جو حضرت کرشن علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے مگر اس میں بھی عام طور پر لڑائیوں اور تاریخی واقعات کا ہی ذکر ہے آپ کے دعویٰ کی تفصیلات اس سے نہیں ملتیں.بہرحال اسرائیلی نبی جن کی تاریخ ایک حد تک محفوظ ہے.ان کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کومخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو بھی موسیٰ جیسا نبی ہے.یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جنس میں شامل تھے جس جنس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے.اب یہ ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
Page 37
کو جو کمالات نبوت عطا کئے گئے تھے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ان سے زیادہ ثابت ہوجائیں تو لازماً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا ملنا بھی ثابت ہو جائے گا.کیونکہ خدا تعالیٰ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قسم سے ہیں اور آپ کے کمالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کمالات کے مشابہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ جوچیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے وہ دوسروں سے بڑھ کر ہے.یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام والے کمالات بھی آپ کو ملے اور پھر ان سے بڑھ کر ملے.اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑے بڑے واقعات کیا گذرے تھے اور پھر ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے مقابلہ کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس کس رنگ میں کو ثر عطا فرمایا ہے.اس بارہ میں جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم کی حضرت موسیٰ پر پہلی فضیلت (۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام الٰہی پھیلانے اور لوگوں کو روحانی علوم سکھانے کے لئے آئے تھے اور یہ سیدھی بات ہے کہ ظاہری علوم اس کام میں بہت ممد ہو تے ہیں.علم سیکھانے کے کام میں پڑھے لکھے آدمی کے لئے بہت آسانی ہو تی ہے.چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تو آپ پڑھے لکھے تھے.قرآن کریم اور تورات دونوں سے اس کا پتہ چلتا ہے.گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبیوں کا کام دیا گیاتودنیوی ہتھیار آپ کے پاس موجود تھایعنی آپ پڑھے لکھے تھے اور اپنے کام کو احسن طریق پر سرانجام دے سکتے تھے.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی کام سپرد ہوا تو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے.مگر اَن پڑھ ہو نے کے باوجود آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کامیابی حاصل کی.یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے.دوسری بڑی فضیلت (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جو متمدن تھی.آپ جب مصر میں تشریف لائے اس وقت مصری قوم چوٹی کی قوم سمجھی جاتی تھی اور چونکہ بنی اسرائیل بھی اس کے ساتھ رہتے تھے اس لئے اسرائیلی قوم بھی پڑھی لکھی اور متمدن تھی اور پڑھے لکھے اور متمدن لوگوں کو دینی علوم سکھانا زیادہ آسان ہو تا ہے.ان میں نظام کو قائم کرنا اور ان کے اندر جماعتی روح پیدا کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کی طرف آئے تھے جو غیر متمدن تھی اور ظاہری علوم سے بالکل ناآشنا تھی.چنانچہ حضرت عمرؓ کے زمانہ کا یہ واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کسریٰ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک دفعہ کسریٰ
Page 38
نے درباریوں سے کہا تم ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ.معلوم ہوتا ہے تم ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے.میں انہیں روپے دے دوں گا اور یہ خوش ہو کر واپس چلے جائیں گے.چنانچہ کسریٰ نے اسلامی لشکر کے جرنیل کو کہلا بھیجا میرے پاس اپنا وفد بھیجو جب وہ وفد کسریٰ کے دربار میں آیا تو کسریٰ نے کہا کہ تم لوگ وحشی اور مردار خور ہو اور گوہیں کھاتے ہو تمہارا بادشاہتوں کے ساتھ کیا واسطہ ہے.میں تم کو روپے دیتا ہوں تم واپس جا کرانہیں خرچ کرو اور گھروں میں آرام سے بیٹھو.اگر تم واپس جانے کے لئے تیار ہو جاؤ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ہر افسر کو دو اشرفیاں اور ہر سپاہی کو ایک اشرفی دوں گا.جب کسریٰ اپنی بات ختم کر چکا تو وفد کے سردار نے جو ایک صحابیؓ تھے جواب دیا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے.ہم واقعہ میں ایسے ہی تھے ہم وحشی تھے، ہم مردار خور تھے، ہم گوہیں کھاتے تھے، ہم یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم اپنی ماؤں کے ساتھ شادیاں کرلیتے تھے اور ہمارے اندر یہ سارے نقائص موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کو ہم نے مان لیا.اس لئے اب ہماری حالت اور ہے اب ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے.اب ہم اس قسم کی لالچوں میں آنے والے نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی چھڑچکی ہے اب اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہو گا اشرفیوں اور لالچوںسے نہ ہو گا.یا ہم تم کو ماریں گے یا خود اس لڑائی میں شہید ہو جائیں گے.بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا جاؤ اور ایک مٹی کا بورا لاؤ.وہ نوکر گیا اور ایک مٹی کا بورا لے آیا.کسریٰ نے اس صحابی ؓ سے کہا.ذرا آگے آؤ.وہ آگے گئے تو بادشاہ نے اپنے نوکر سے کہا مٹی کا بورا ان کے سر پر رکھ دو.وہ صحابی ؓ انکار بھی کر سکتے تھے مگر وہ بڑے ادب سے جھک گئے اور اس بورے کو اپنے سر پر اٹھا لیا.کسریٰ نے کہا جاؤ میں تم کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں یہ مٹی میں تم پرڈالتا ہوں.وہ صحابی ؓ چھلانگ لگا کر وہاں سے نکلے اور اپنے ساتھیوں سے کہا چلو بادشاہ نے خود اپنے ہاتھوں سے ایران کی زمین ہمارے حوالہ کر دی ہے.بادشاہ مشرک تھا اور مشرک وہمی ہو تا ہے وہ یہ الفاظ سن کر کانپ اٹھا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا دوڑو اور انہیں واپس لاؤ.مگر وہ اس وقت تک گھوڑوں پر سوار ہوکر بہت دور نکل چکے تھے(البدایۃ والنـھایۃ سنۃ ۱۴ھـ غزوۃ القادسیۃ).غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس قوم اور ملک میں کام کیا وہ قوم اور ملک سب سے زیادہ متمدن تھے.ان کے جو قدیم آثار ملتے ہیں ان سے بھی اس چیز کا پتہ چلتا ہے.اس زمانہ کی عمارتوں کو لے لو آج کل کی عمارتیں ان کے سامنے بالکل ہیچ معلوم ہو تی ہیں.سائنس کو دیکھو تو انہوں نے مردوں کو مصالحے لگا کر اس طرح رکھا ہے کہ وہ اب بھی زندہ معلوم ہو تے ہیں.میں نے وہ ممیاں خود دیکھی ہیں ان پر سے کپڑے اتار دو تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گویا کوئی آدمی سویا ہوا ہے.صرف کچھ دبلا سا ہوگیا
Page 39
ہے.یوروپ والے آج تک کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ بھی ایسا کرسکیں مگر اس میں کامیاب نہیں ہوئے.اب انہوں نے ممیوں سے مصالحے نکال کر ان کا انیلے سز ANALYSIS کیا ہے اور وہ ایک حد تک ان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں.مگر پھر بھی ان کا مصالحہ صرف دس بارہ سال تک جاتا ہے.لیکن مصری مردے ہزاروں سال سے محفوظ چلے آرہے ہیں ۳۴ سو سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ کے مردے اب تک محفوظ ہیں.یہ کتنی بڑی ترقی تھی جس کا مقابلہ آج کل کی قومیں بھی نہیں کر سکیں.پھر مصری قوم میں سو نے کا کام نہایت اعلیٰ درجہ کا ہو تا تھا جو ان کی ترقی کی ایک بیّن علامت ہے.اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مصری قوم کے ساتھ رہنے والے لوگ کتنے متمدن اور ترقی یافتہ ہو ں گے.پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کام لیا جو متمدن تھی اور ظاہری علوم سے بہرہ ور تھی.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے کام لیا جو اپنی ماؤں کا ادب کرنا بھی نہیں جانتے تھے بلکہ ان سے شادی کر لیتے تھے(روح المعانی زیر آیت وَ لَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُ كُمْ) اور دوسرے نقائص بھی ان میں پائے جاتے تھے.پھر آپ اپنے کام میں کامیاب ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کامیاب ہوئے.تیسری فضیلت (۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ کام بہت بڑا ہے مجھ سے نہیں ہوسکے گا.میرے ساتھ ایک اور آدمی بطور مدد گار مقرر کر دیجئے اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اَھْلِیْ (طٰہٰ :۳۰) وہ مدد گار بھی مجھے میرے رشتہ داروں میں سے ہی ملنا چاہیے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احساس دیکھو کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت کے مقام پر سرفراز کیا گیا تو آپ نے کہا میں یہ کام نہیں کرسکتا خدا آپ کے سپرد ایک کام کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام انکار کرتے ہیں.ہم مان لیتے ہیں کہ یہ انکسار تھا مگر انکساری کی بھی کوئی حد ہو نی چاہیے.خدا تعالیٰ نے بار بار آپ سے کہاکہ تم فرعون کی طرف جاؤ مگر جیسا کہ تورات سے معلوم ہو تا ہے آپ جواب میں انکار ہی کرتے چلے گئے.پھر آپ کا اپنے ساتھ ایک مدد گار مانگنے پر اصرار کرنا اور یہ کہنا کہ وہ ہو بھی میرے خاندان میں سے ہی، یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام با وجود خدا تعالیٰ کے حکم کے اپنے کام میں دنیوی سامانوں کی مدد بھی چاہتے تھے.اس کے مقابلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کے زمانہ سے کتنے دور تھے (موسیٰ علیہ السلام کے تو قریب کے ہی زمانہ میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم السلام کئی انبیاء گذرے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ۲۵۰۰ سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمٰعیل علیہ السلام ہوئے اس کے بعد آپ کی قوم میں کوئی نبی نہیں آیا) مگر آپ کی معرفت دیکھو آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اِقْرَاْ جس کے معنے یہ ہیں کہ تو پڑھ.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
Page 40
نے فرمایا مَا اَ نَا بِقَارِیءٍ میں تو لکھا پڑھا نہیں ہوں.اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کتاب آپ نے پڑھنی تھی.جبریل علیہ السلام کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کہ وہ آپ سے کہتے یہ کتاب پڑھو اور جب کوئی وجود بغیر کتاب کے آئے اور کہے پڑھ تو اس کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ جو کچھ میں کہتا جاتا ہوں تو اس کو دہرا تا جا پس جب آپ سے فرشتے نے کہا پڑھ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اے شخص ( اس وقت آپ نبی نہیں تھے ) جو کچھ میں کہتا جاؤں تم اسے دہراتے جاؤ.لیکن آپ فرماتے ہیں مَا اَ نَا بِقَارِیءٍ میں تو لکھا پڑھا نہیں ہوں.یہ تھی آپ کی انکساری.آپ سمجھتے تھے کہ میرے سپرد کوئی بڑا کام ہو نے والا ہے مگر خدا تعالیٰ بڑی شان والا ہے اور میں بندۂ عاجز ہوں.ہو سکتا ہے کہ میں وہ کام پوری طرح سرانجام نہ دے سکوں اس لئے آپ نے کہا میں لکھا پڑھا نہیں ہوں.فرشتے نے دوبارہ کہا اِقْرَاْ پڑھ.آپ نے پھر فرمایا مَا اَ نَا بِقَارِیءٍ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا.پھر تیسری دفعہ فرشتے نے کہا اِقْرَاْپڑھ تو آپ پڑھنے لگ گئے.یہ تھا انکسار.موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ بار بار انکار نہیں کرتے گئے بلکہ جب آپ نے سمجھا کہ خدا تعالیٰ اس امر کو بہر حال میرے ہی سپرد کرنا چا ہتا ہے تو آپ نے اس کا حکم فوراً مان لیا اور سمجھ لیا کہ اب انکار کرنا سوءِ ادبی ہے.پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی مدد گار دیں بلکہ کہا کہ جب منشاء الٰہی ہی یہ ہے کہ میں اس بوجھ کو اٹھاؤں تو میں اس کو اکیلا ہی اٹھاؤں گا.یہ ہے آپ کی فضیلت جو آپ کے مقام کو نمایاں کرنے والی ہے.موسیٰ علیہ السلام کے سپرد ایک چھوٹا سا کام ہوا تو انہوں نے مدد گار مانگا مگر آپ کے سپرد اس سے بہت بڑا کام ہوا تو فرمایا میں اکیلے ہی اس کام کو سرانجام دوں گا اور آپ نے کامیاب طور پر وہ کام سرانجام دے دیا.یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے.چوتھی فضیلت (۴)حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کتاب ملی مگر فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی باوجود اس کے کہ ان کے بعد متواترنبی آئے وہ محفوظ نہ رہ سکی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی باوجود اس کے کہ آپ کے بعد تیرہ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا وہ اب تک محفوظ چلی آرہی ہے.جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ تورات بگڑ چکی تھی.یہودی کتب میں لکھا ہے کہ جب بخت نصربادشاہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے شہروں اور گرجوں کو توڑا اور اس نے یہودیوں کو افغانستان اور ایران میں بسا دیا اور بعض کو کشمیر بھیج دیا تو اس وقت تورات کے سارے نسخے جل گئے تھے یا پھٹ کر ضائع ہو چکے تھے.پھر عزرا نبی اور چار پانچ زود نویسوں نے مختلف حفاظ کے ساتھ مل کر کتاب جمع کی.دیکھو APOCRYPHA II ESADRAS 14 گویا چھ سو سال کے بعد ہی کتاب ختم ہو گئی.اس کے
Page 41
علاوہ خود تورات کی اندر ونی شہادت اس بات پر موجود ہے کہ وہ محرف ومبدل ہو چکی تھی.چنانچہ استثناء کے آخر میں لکھا ہے’’پس خدا وند کے بندہ موسیٰ نے خدا وند کے کہے کے موافق وہیں موآب کے ملک میں وفات پائی ‘‘ (۵/۳۴) کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کا الہام کہلا سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے ’’اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خدا وند نے رو برو باتیں کیں نہیں اٹھا ‘‘(۱۰/۳۴) کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کا الہام ہوسکتا ہے؟ پھر لکھا ہے ’’اور اس نے اسے موآب کی ایک وادی میں دفن کیا پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں ‘‘ (۶/۳۴) یہ بھی ایک ایسا فقرہ ہے جو کسی شخص نے بعد میں لکھ کر تورات میں شامل کر دیاہے.ان حوالہ جات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اگر قرآن کریم میں ہی یہ لکھا ہو کہ پھرمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کیا عیسائی اور ہندو وغیرہ یہ مان لیں گے کہ یہ محفوظ کتاب ہے؟ وہ فوراً یہ حوالہ نکال کر آگے رکھ دیں گے.اور کہیں گے کہ تمہاری کتاب محرف و مبدل ہو چکی ہے مگر تورات میں یہ سب باتیں لکھی ہیں کہ پھر وہ مر گیا.اس کے مرنے پر بنی اسرائیل چالیس دن تک روتے رہے اور یہ کہ اس جیسا کوئی آدمی اب تک بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوا.اس کی قبر کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ کتاب نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اور یہ کہ آپ کے بعد آنے والے نبی بھی اس کو محفوظ نہیں رکھ سکے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ تیرہ سو سال کے بعد اب بھی محفوظ ہے اور اس کا ایک شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوا.حالانکہ آپ کے بعد اس عرصہ میں کوئی نبی بھی نہیں آیا.میور اور نولڈ کے جیسے شدید دشمن بھی اس بات کا اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکے کہ قرآن کریم اسی شکل و صورت میں محفوظ ہے جس شکل و صورت میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا.میور جو اسلام کا شدید ترین دشمن ہے اور جو قدم قدم پر اسلام کی دشمنی کرتا ہے لکھتا ہے کہ THERE IS OTHERWISE EVERY SECURITY INTERNAL AND EXTERNAL THAT WE POSSESS THE TEXT WHICH MOHAMMAD HIMSELF GAVEFORTH AND USED یعنی اس کے علاوہ ہمارے پاس ہر ایک قسم کی ضمانت موجود ہے اندرونی شہادت کی بھی اور بیرونی کی بھی کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے وہی ہے جو خود محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اور اسے استعمال کیا کرتے تھے.(LIFE OF MOHAMMAD PAGE:28 ) گویا شدید سے شدید دشمن بھی قرآن کریم کی حفاظت کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکا.یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے.
Page 42
کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی تو مانتے ہیںکہ حضرت مرزا صاحب (علیہ الصلوۃ والسلام ) نبی ہیں پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لئے کوئی نبی نہیں آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب قرآن کریم کی ظاہری شکل کو محفوظ کرنے کےلئے نہیں آئے.آپ آتے یا نہ آتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کے سامان بہم پہنچا دیئے تھے اور قرآن کریم میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا تھا.آپؑکا آنا اس معجزہ کو ہرگز مشتبہ نہیں کرسکتا کیونکہ آپ کا قرآن کریم کی حفاظت ظاہری میں کوئی دخل نہیں.خواہ قیامت تک ایک مجدد بھی نہ آتا یا نہ آئے تب بھی قرآن کریم کی ظاہری صورت محفوظ رہے گی اور کبھی نہ بدلے گی جس طرح وہ آج تک نہیں بدل سکی.پانچویں فضیلت (۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ملک سے نکلے اور فرعون نے آپ کا تعاقب کیا تو جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے آپ کی قوم سخت گھبرا گئی اور اس نے سمجھا کہ اب وہ فرعون کی گرفت سے نہیں بچ سکتی.چنانچہ انہوں نے چلّا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُوْنَ (الشعرآء:۶۲) اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے.اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کَلَّا اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَھْدِیْنِ(الشعرآء:۶۳) ایسا ہر گز نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہ ہمیں دشمنوں کے حملہ سے بچا لے گا.چنانچہ خدا تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت مکہ سے نکلے اور غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تو دشمن ایک تجربہ کار کھوجی کی راہنمائی میں آپ کو تلاش کرتے کرتے عین اس غار کے منہ پر جاپہنچا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپے ہوئے تھے اس وقت کھوجی نے انہیں کہا کہ محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) یقیناً یہاں چھپے ہوئے ہیں اور اگر وہ اس غار میں نہیں تو پھر آسمان پر چلے گئے ہیں دشمن اس وقت آپ سے اتنا قریب تھا کہ حضرت ابو بکرؓجو آپ کے ساتھ تھے گھبرا گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ! دشمن تو اس قدر نزدیک ہے کہ اگر وہ ذرا جھک کر اندر جھانکے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے.آپ نے اس وقت بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ابو بکر گھبراتے کیوں ہو اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا (التوبۃ:۴۰) اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا.چنانچہ باوجود اس کے کہ دشمن عین اس مقام پر پہنچ گیا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم تھے پھر بھی وہ خائب و خاسر واپس چلا گیا اور وہ آپ کو پکڑنے میں ناکام رہا.گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری مدد کرے گا لیکن اگرغور کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کا تباہ ہوجانا اس طرح تھا کہ دشمن اب بھی کہہ دیتا ہے کہ موسیٰ اور آپ کی قوم سمندر سے گذرے ہی اس وقت تھے جب
Page 43
جزر کا وقت تھا.جب ٹائیڈ TIDE کا وقت آیا تو فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب گئے.اس میں معجزہ اور نشان کی کون سی بات ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اس طرح بچایا کہ دشمن آپ کے قدموں کے نشانا ت کو دیکھتا ہوا غار ثور پر پہنچا اور پھر بھی وہ آپؐکو نہ دیکھ سکا حالانکہ ان کا معتبر کھوجی ساتھ تھا اور اس نے کہا بھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہاں چھپے ہوئے ہیں اور اگر وہ یہاں نہیں تو پھر آسمان پر چلے گئے ہیں.مگر اس کے اس قدر یقین دلانے کے باوجود دشمن کو اتنی تو فیق نہ ملی کہ وہ جھک کر غار کے اندر دیکھ لے اور وہ ناکام و نامراد واپس چلا گیا.اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لئے کفار مکّہ نے ایک سو اونٹ کا انعام مقرر کر دیا (السیرۃ النبویۃ لابن ھشام ھجرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم) یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اس کو حاصل کر نے کے لئے عرب چاروں طرف دوڑ پڑے.انہوں نے خیال کیا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مل گئے تو سو اونٹ مل جائیں گے اور گھر کی حالت سدھر جائے گی سو اونٹ اس وقت کے لحاظ سے بڑا بھاری انعام تھا بلکہ آج کل کے لحاظ سے بھی یہ بڑا بھاری انعام ہے.آج کل گورنمنٹ مجرموں کو پکڑنے کے لئے پانچ پانچ ہزار یا دس دس ہزار روپیہ انعام رکھتی ہے.اگر سو اونٹ کی قیمت کا اندازہ اس زمانہ کے لحاظ سے کیا جائے تب بھی کم از کم ساٹھ ستر ہزار روپیہ کاانعام بنتا ہے غرض یہ ایک بہت بڑا انعام تھا جس کو حاصل کرنے کے لئے ویسے تو بہت سے افراد باہر نکلے لیکن ایک شخص اتفاقاً اس راستہ پر جاپہنچا جس رستہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے.اس شخص نے آپ کو دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ وہ آپ کو پکڑنے میں اب ضرور کامیاب ہو جائے گا.جس وقت وہ قریب پہنچا تو اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا.اس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اس موقعہ پر فوراً تیر نکال کر فال لی کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں.فال نکلی کہ نہیں بڑھنا چاہیے مگر سو اونٹ کا انعام تھا رہ نہ سکا.پھر ایڑ لگا کر پاس پہنچا مگر پھر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور اب کی دفعہ پیٹ تک دھنس گیا.وہ گھبرا یا اور سمجھا کہ کوئی اور بات ہے.چنانچہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت ادب سے حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں امان چاہتا ہوں میں اب سمجھ گیا ہوں کہ آپ خدا تعالیٰ کے نبی ہیں.میں آپ کے تعاقب میں آیا تھا مگر واپس جاتا ہوں.مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور جب آپ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ ضرور غالب آجائیں گے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک کاغذکا پرزا لکھ دیں تاکہ جب خدا تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
Page 44
نے اسی وقت حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا اور آپ نے اسے لکھ کر دے دیا کہ خدا تعالیٰ جب مسلمانوں کو غلبہ عطا کرے تو اس شخص سے نیک سلوک کیا جائے.(بخـاری کـتـاب مناقب الانصار باب ھجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم) گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا آپ کے ساتھ دو دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ دشمن نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر دونوں دفعہ وہ ناکام رہا.پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا تو اس نے آپ کو دیکھ لیا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن باوجود پاس پہنچ جانے کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکا.دوسری دفعہ جب دشمن نے آپ کو گرفتار کرنا چا ہا تو اس وقت بھی وہ ناکام رہا اور نہ صرف ناکام رہا بلکہ اس نے آپ کی برتری کو تسلیم کیا.پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کو خدا تعالیٰ اس وقت نظر آیا جب وہ ڈوب رہا تھا.چنانچہ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لاتا ہوں.اس کے جوا ب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا تو آخری وقت میں ایمان لایاہے اب تجھے نجات تو نہیں دی جا سکتی مگر تیرے بدن کو نجات دے دی جائے گی تاکہ تو دوسروں کے لئے عبرت کا موجب ہو.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لئے جو دشمن نکلا وہ زندہ رہا اور اپنی زندگی میں اس نے تسلیم کر لیا کہ آپ خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں.بلکہ اس نے آپ سے یہ اقرار نامہ لکھوالیا کہ جب خدا تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کرے تو مجھ سے حسن سلوک کیا جائے اور پھر خدا تعالیٰ نے اسے آپ کے غلبہ تک زندہ رکھا اور مسلمانوں نے اس سے حسن سلوک کیا.یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے.چھٹی فضیلت (۶)ایک فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تو تباہ ہوا لیکن دشمن کے تباہ ہو جانے کے بعد اس کے ملک پر آپ کو غلبہ میسر نہیں آیا.بے شک بعض جاہل علماء یہ کہہ دیتےہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں اس ملک پر قبضہ مل گیا تھا اور ایک آیت کے غلط معنے کر کے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی بائبل سے ثابت ہو تا ہے.یوں ہی کہہ دینے سے آپ کو مصر کے ملک پر غلبہ حاصل ہو گیا تھا کیا بنتا ہے.واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے بعد میں وہ جنگلوں میں پھرتے رہے اور اپنی منزلِ مقصود کو ایک لمبے عرصہ تک نہ پا سکے.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جب شکست کھائی تو آپ ان کے ملک پر بھی قابض ہو گئے اور یہ آپ کی موسیٰ علیہ السلام پر برتری ہے.ساتویں فضیلت (۷)حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سب سے پہلا مقابلہ ریڈ سیRED SEA میں
Page 45
پیش آیا لیکن وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی.بنی اسرائیل بھاگتے ہوئےآرہے تھے وہ دل میں ڈر رہے تھے کہ کہیں فرعون ان کے تعاقب میں نہ آجائے چنانچہ جب انہوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے گھبرا کر کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَکُوْنَ.اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے وہاں موسیٰ کی قوم نے کوئی بہادری نہیں دکھائی.پھر جب لڑائی کا وقت آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ جاؤ اور دشمن سے لڑو تو انہوں نے لڑائی کرنے سے انکار کر دیا.حالانکہ کنعان کاملک بہت چھوٹا ہے.سارے فلسطین کا رقبہ دس ہزار مربع میل ہے مگر کنعان کا رقبہ دو تین ہزار مربع میل ہے.اتنے چھوٹے سے علاقہ کو فتح کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیامگر قرآن کریم اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے تائیدات سماوی کو دیکھ لیا ہے تم اس ملک پر حملہ کرو اور اسے فتح کرکے اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کرو تو ان کی قوم نے کہا اِذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ(المآئدۃ:۲۵) اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہاراخدا دشمن سے لڑتے پھرو ہمیں تو ملک فتح کر کے دے دو گے تو ہم لے لیں گے لڑائی کرنے کے لئے ہم تیار نہیں.تم کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ تم کویہ ملک دے گا.اب وہ خودہی دے تو دے ہم کیوں لڑتے پھریں.کیا اس کا ہمارے ساتھ وعدہ نہیں تھا.گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آٹھ دس سال کی صحبت نے ان کے اندر اتنا بھی عرفان پیدا نہ کیا کہ خدا تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کر نے کے لئے بندے کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے.انہوں نے موسٰی کو صاف جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ(المآئدۃ:۲۵) اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں د شمن سے لڑتے پھرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ شام سے ایک قافلہ آرہا ہے اور وہ قبائل کومسلمانوں کے خلاف اکسا تا آرہا ہے تو آپ اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر اس کی شرارتوں کا سدّ باب کر نے کے لئے نکلے.سارے صحابہ ؓ آپ کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹا سا قافلہ ہے جس کے اثر کو زائل کرنا مقصود ہے تا عرب کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے میں دلیر نہ ہو جائیں کوئی لڑائی تو ہے نہیں ادھر آپؐکو الہام میں بتایا گیا کہ مکہ سے بھی ایک بڑا بھاری لشکر اس قافلہ کی مدد کے لئے آرہا ہے.مگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ صحابہ کو بتانا نہیں یہ ان کے لئے امتحان کا وقت ہے.آپؐچلتے چلے گئے.جب آپ کئی منزلیں آگے نکل گئے تو آپ نے صحابہؓ کو جمع کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ دشمن کا ایک بڑا بھاری لشکر مکہ سے آرہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا مقابلہ یا تو اس لشکر کے ساتھ کرا دے گا اور یا شام سے آنے والےقافلہ کے ساتھ کرا دے گا.ابھی آپ پر اس کا پورا اظہار نہیں ہوا تھا کہ آخر کس سے مقابلہ کرنا پڑے گا(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام غزوۃ بدر الکبرٰی).پھر آپ اور آگے چلے
Page 46
اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیاکہ مقابلہ یقینی طور پر مکہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ ہو گا قافلہ کے ساتھ نہیں ہوگا.یہ لشکر مسلمانوں سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھا اور طاقت میں بھی ان سے بڑھ کر تھا.وہ سب آزمودہ کار سپاہی تھے اور پھر پو ری طرح مسلّح تھے اور اگرتمدن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دونوں لشکر برابر تھے.مسلمان بھی عرب تھے اور مقابلہ پر دشمن بھی عرب تھا.مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کنعانی لوگ محض قبائلی گروہ تھے اور بنی اسرائیل ایک متمدن اور منظّم قوم تھی یعنی کنعانی لوگ جاہل اور غیر تعلیم یافتہ تھے اور ان کے مقابلہ میں بنی اسرائیل منظّم اور متمدن لوگ تھے.مگر باوجود اس کےجب لڑائی کا وقت آیا تو انہوں نے انکار کر دیا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے یہ نہیں کہا حالانکہ طاقت کو دیکھا جائے تو دشمن بہت زیادہ مضبوط اور طاقت ور تھا.اور پھر مسلمانوں سے بہت زیادہ تجربہ کار بھی تھا.مسلمان اتنے تجربہ کار نہیں تھے بلکہ ان میں سے ایک حصہ تو مدینہ والوں کا تھا جنہوں نے کسی بڑی لڑائی میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا تھا(الطبقات الکبرٰی لابن سعد غزوۃ بدر) پھر تعداد کو لیا جائے تو مسلمان صرف تین سو تیرہ تھے اور دشمن کا لشکر ایک ہزار تھا.پھر دشمن کے پاس سامان جنگ بھی موجود تھا اور اس کے پاس گھوڑے بھی تھے اور جتنا گھوڑا جنگ میں کام آ سکتا ہے اتنا اونٹ کام نہیں آسکتا.مسلمانوں کے پاس سارے لشکر میں صرف ایک گھوڑا تھا.گویا مسلمانوں کا لشکر کلّی طور پر کمزور تھا اور دشمن کئی گنا طاقت ور تھا.اس وقت آپؐنے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا اب مجھے یقینی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارا اس لشکر سے مقابلہ ہو گا جو مکہ سے ابو جہل کی کمان میں آ رہا ہے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مہاجرین یکے بعد دیگرے اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لڑیں گے ایک مہاجر جب بیٹھ جاتا تو دوسرا اٹھتا پھر تیسرا اٹھتا پھر چوتھا اٹھتا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے جاتے بتاؤ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے.انصار بھی اس لشکر میں تھے مگر وہ خاموش تھے.وہ یہ سمجھتے تھے کہ مکہ سے جو لشکر آرہا ہے اس میں مہاجرین کے بھائی بند ہیں.اگر ہم نے کہا کہ ہم لڑیں گے تو مہاجرین کے چونکہ وہ بھائی بند ہیں.کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے اور کوئی بھتیجا ہے.اس لئےان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گا کہ انصار کو ہم سےمحبت نہیں تبھی وہ اس جوش سے ہمارے رشتہ داروں کا مقابلہ کر نے کے لئے تیار ہیں مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کے اے لوگو مجھے مشورہ دو تو ایک انصاری اٹھے اور انہوں نےکہا یا رسول اللہ شاید آپ کی مراد ہم انصار سے ہے ورنہ آپ کو رائے تو مل رہی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مہاجرین کے ادب کی وجہ سے اب تک چپ تھے ہم ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہم لڑائی کے لئے تیار ہیں تو مہاجرین کے جذبات کو ٹھیس لگے گی.پھر اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ جب ہم میں سے پہلی دفعہ بہتّر۷۲ آدمی آپ کے پاس گئے اور
Page 47
انہوں نے آپ کی بیعت کی اس وقت ہم نے آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا تو ہم آپ کی اپنی جان و مال سے حفاظت کریں گے.لیکن اگر آپ مدینہ سے باہر نکل کر دشمن سے لڑے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہو گی کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ دشمن سے باہر نکل کر لڑسکیں.آپ جو بار بار پو چھتے ہیں تو شاید آپ کا اشارہ اس معاہدہ کی طرف ہے کیونکہ یہ لڑائی مدینہ سے باہر ہو نے والی ہے.آپؐنے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے.اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ جب ہم نے آپ سے وہ معاہدہ کیا تھا اس وقت آ پ کی شان ہم پر ظاہر نہیں ہوئی تھی اب ہم کچھ عرصہ تک آپ کے ساتھ رہے ہیں اور ہم نے آپ کے اخلاق اور تعلق باللہ کو دیکھ لیا ہے اور آپ کی شان ہم پر ظاہر ہو چکی ہےاس لئے اب کسی معاہدے کا سوال ہی نہیں.یا رسول اللہ سامنے سمندر ہے (بدر کے میدان سے کچھ فاصلہ پر سمندر تھا جس کی طرف اس انصاری نے اشارہ کیا اور یہ بھی اس لئے کہ عرب لوگ پانی سے بہت ڈرتے تھے) آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے اور ذرا بھی چون و چرانہیں کریں گے پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اگر لڑائی ہی مقدر ہے تو ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے.آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو روندتا ہوا نہ گذرے.اس واقعہ کو دیکھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اس واقعہ کو سامنے رکھیں جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ(المآئدۃ:۲۵) اور پھر غور کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے صحابہؓ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کتنا عظیم الشان فرق ہے.معلوم ہوتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ نے اس انصاریؓ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھتے ہوں کہ آپ کی اُمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح پیچھے ہٹ رہی ہے.چنانچہ اس انصاریؓنے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تو جا اور تیرا رب دونوں دشمن سے لڑتے پھرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں.بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن ہماری لاشوں پر سے گذرے تو گذرے ورنہ جب تک ہم زندہ ہیں دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا.یہ کتنی زبر دست فو قیت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے.آٹھویں فضیلت (۸) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ کی قوم نے کہا اِذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ(المآئدۃ:۲۵) تو خدا تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم نے بہت بڑی گستاخی کی ہے اس گستاخی کی
Page 48
وجہ سے ہم اسے اس فتح سے محروم کرتے ہیںجس کا ہم نے وعدہ کیا تھا.جاؤ اب چالیس سال تک جنگلوں میں آوارہ پھرو اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو.پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا..چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو چالیس سال تک جنگلوں میں بھٹکنے کے بعد کنعان ملا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو آپ کی وفات کےبارہ سال کے عرصہ میں ہی ساری متمدن دنیا پر حکومت مل گئی.یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہے.نویں فضیلت (۹) ایک اور امتیازی خصوصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں یہ حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوگیا مگر آپؐکا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو گا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موسوی سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک ممتد رہا بلکہ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک بھی پہنچا مگر صرف نام کے طور پر.ورنہ حضر ت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ہی لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں.بلکہ انہوں نے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو گا اور قیامت تک چلتا چلا جائے گا.دسویں فضیلت (۱۰)حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری خلیفہ یعنی مسیحؑ ناصری کی جماعت نے آپ کو جواب دے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی افضلیت کا انکار کر دیا.اس میں کچھ دخل اس بات کا بھی تھا کہ حضرت مسیح کی زبان سے بعض ایسے ذو معنے فقرے نکلے جن سے آپ کی قوم دھوکا کھاگئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ بیٹھی لیکن ہمارے سلسلہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ السلام نے جو محمدی سلسلہ کے آخری خلیفہ ہیں اگر کچھ کہا تو یہ کہ ؎ وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے یعنی مجھے جو بھی کمالات ملے ہیں وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل ہیں یہ خیال نہ کرنا کہ میں آپ کے مدّ ِمقابل کی چیزہوں.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہا.لیکن ہمارے بانیٔ سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خلیفہ نے نہایت ادب کے ساتھ کہا.؎ وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے یعنی مجھے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہی نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک شعر ہے جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں لیکن ہمیں تو اس میں لطف
Page 49
ہی آتا ہے.آپ فرماتے ہیں ؎ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے اس پر لوگ یہ اعتراض کر تے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے آپ کو ابن مریم ؑ سے افضل بتایا ہے.حالانکہ آپ نے اپنے آپ کو ابن مریمؑ سے افضل نہیں بتایا بلکہ احمد ؐ کے غلام کو افضل قرار دیا ہے اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے.یہاں احمد سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی بڑا ہے اور جس کا غلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہو اور افضل ہو وہ خود تو ان سے بدر جہا افضل ہو گا.غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ موسوی سلسلہ کے آخری خلیفہ کی جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سلسلہ کے بانی سے افضل قرار دے دیا.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خلیفہ نے اپنے آقا کی شان اور عظمت کو قائم کیا اور اس نے دنیا میں بڑے زور سے یہ اعلان کیا کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہی پایا ہے.گیارھویں فضیلت (۱۱) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ مستقل نبی تھے.گو وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے مگرنبوت کا مقام انہوں نے براہ راست حاصل کیا تھا.گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط کے بغیر انہیں یہ مقام ملا تھا.موسوی تعلیم ایسی نہ تھی کہ وہ کسی کو نبوت کے مقام تک پہنچا سکتی.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپؐکے اتباع خواہ نبی ہوں آپؐکے فیض سے نبی بننے والے ہیں اور انہیں جو کچھ ملے گا فیض محمدی سے ہی ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تو تھے مگر نبوت کے مقام پر وہ براہ راست پہنچے تھے.موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں یہ خوبی نہ تھی کہ وہ کسی کو نبوت کے مقام تک پہنچا سکے لیکن قرآن مجید میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ اس پر عمل کر نے سے انسان نبوت کے مقام پر بھی پہنچ سکتا ہے مگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع اور قرآن کریم کا خادم ہی رہتا ہے.بارھویں فضیلت (۱۲)حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا جو بعض اوقات سانپ بن جاتا تھا جو ایک کاٹنے والی چیز ہے.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شمشیر قرآن ملی جو ہمیشہ رحمت ہی رحمت بنی رہتی ہے.اللہ تعالیٰ اس شمشیر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتا ہے وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا (الفرقان:۵۳) تو قرآن کریم کو
Page 50
لے اور اس سے جہاد کرتا چلا جا.مادی تلواروں کی لڑائیاں تو معمولی ہو تی ہیں اور جلد ختم ہو جاتی ہیں مگر قرآن کریم ایک ایسی تلوار ہے جو دشمن کے مقابلہ میں ہمیشہ کام آنے والی ہےاور جس کے اثرات رحمت کی صورت میں ہی ظاہر ہو تے ہیں.یہی وجہ ہے کہ آپ کو بار بار رحمۃ للعالمین کہا گیا ہے اور آپ نے تعلیم بھی ایسی ہی دی ہے جس میں نرمی اور محبت کو تعذیب اور انتقام پر ترجیح دی گئی ہے.مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی کہ اگر تمہیں کوئی تھپڑ مارے تو تم بھی اسے تھپڑ مار و.اگر کوئی شخص تمہاری آنکھ نکال دے تو تم بھی اس کی آنکھ نکال دو.اگر کوئی شخص تمہارا دانت توڑدے تو تم بھی اس کا دانت توڑ دو.مگر اسلام کہتا ہے کہ تم جو بھی قدم اٹھاؤ سوچ سجھ کر اور حالات کو دیکھ کر اٹھا ؤ اگر مصلحت اس میں ہو کہ معاف کر دیا جائے تو اپنے دشمن کو معاف کر دو.اسے سزا دینے پر اصرار نہ کرو.کیونکہ تمہاری غرض محض اصلاح ہو نی چاہیے نہ کہ انتقام.تیرھویں فضیلت (۱۳)حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ دیا گیا تھا یعنی آپ کا ہاتھ کبھی کبھی چمکا کرتا تھا.لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سِرٰجًا مُّنِیْرًا (الاحزاب:۴۷) کہا ہے اور سورج سارا چمکا کرتا ہے اس کا کوئی ایک حصہ نہیں چمکا کرتا گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف ہاتھ چمکا کرتا تھا.مگر آپؐکا سارا جسم روشن اور منور تھا.پھر سورج ہر وقت روشنی دیتا ہے کبھی کبھار نہیں.مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ صرف کبھی کبھی چمکتا تھا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں راہنما تھے اور ہر وقت آپ کی راہنمائی قائم رہنے والی ہے یہ نہیں کہ کبھی ختم ہو جائے اور کبھی شروع ہو جائے.چودھویں فضیلت (۱۴)حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَ مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ (سبا:۲۹) ہم نے تجھے تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لئے بھیجا ہے.یہ بھی آپ کی فضیلت اور برتری کی ایک روشن دلیل ہے.پندرھویں فضیلت (۱۵) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ آپ کی قوم کے پلوٹھے مرے.پلوٹھوں کا مرنا کوئی بڑا نشان نہیں.مرتا تو ہر ایک ہی ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے پلوٹھے ہی نہیں مرے بلکہ ان کی ساری اولادیں ہی مر گئیں اور پھر زندہ ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئیں.کتنا بڑا دشمن تھا ولید.وہ آپ سے لڑنے کے لئے قبائل کو اکساتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالو.پھر کتنا بڑا دشمن تھا عاص بن وائل.
Page 51
وہ ہر وقت آپ کے خلاف منصوبے سوچتا رہتا تھا اور لشکر تیار کروایا کرتا تھا.پھر کتنا بڑا دشمن تھا ابو جہل.اس نے اپنی ساری عمر ہی آپ کے مقابلہ میں گذار دی.لیکن ولید کا بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایسا ایمان لایا کہ اس کا نام مسلمان بطور یادگار کے استعمال کرتے ہیں.وہ اپنے بیٹوں کا نام خالد رکھتے ہیں اور غیر مسلموں کو ڈراتے ہیں کہ اب بھی ہم میں خالد موجود ہیں.یہ خالد ؓ اس ولید کا بیٹا تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کر کے رہوں گا اور یہ خالد ؓ وہی شخص ہے جس نے اُحد کے موقع پر تاڑلیا تھا کہ مسلمانوں کی پشت ننگی ہے اور اس نے موقع پا کر اوپر سے حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کی فتح عارضی طور پرشکست سے بدل گئی.مگر پھر یہی خالد ؓ اسلام میں داخل ہوئے اور ایسے فدائی اور جان نثار ثابت ہوئے کہ تاریخ بتاتی ہے جب خالد ؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک دوست جو ان سے ملنے کے لئے آیا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ خالد ؓ رو رہے ہیں اس نے تعجب سے کہا خالد ؓ تمہارا رونے سے کیا کام؟ تم نے اسلام کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کی ہیں اب تمہیں خوش ہو نا چاہیے کہ تمہیں بڑے بڑے انعامات ملیں گے خالدؓ نے کہا ذرا آگے آؤاور میری پیٹھ پر سے کپڑا اٹھاؤ.اس نے کپڑا اٹھایا تو خالد ؓ نے کہا، کیا میری پیٹھ پر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں زخم کا نشان نہ ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار کے زخم کے نشان نہ ہوں.خالدؓ نے کہا اچھا اب میرے سینے پر سے کپڑا اٹھاؤ.اس نے آپ کے سینے پر سے کپڑا اٹھایا.خالد ؓ نے کہا دیکھو میرے سینہ اور پیٹ پر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو.انہوں نےکہا اچھا اب میری دائیں ٹانگ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھو کہ کیا میری ٹانگ اور پاؤں پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تلوار کے زخم کے نشان نہ ہوں؟ اس نے کپڑا اٹھا کر دیکھا اور کہا ہر جگہ تلوار کے زخموں کے نشان ہیں.انہوں نے کہا اچھا اب میری دوسری ٹانگ دیکھو اس نے دوسری ٹانگ دیکھی تو وہاںبھی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تلوار کے زخم کے نشانات نہ ہوں.جب وہ اپنے جسم کے تمام نشانات دکھا چکے تو خالد ؓ پھر رو پڑے اور انہوں نے کہا اے میرے دوست میں اس لئے نہیں روتا کہ میں مرنے لگا ہوں بلکہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفرکی حالت میں مقابلہ کیا.پھر خدا تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرمائی او رمیں نے کوشش کی کہ میں اپنا اور اپنے خاندان کا کفارہ شہادت سے ادا کروں اور تم گواہی دے سکتے ہو کہ میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی.میرے سر سے پاؤں تک ایک انچ بھی ایسی جگہ نہیں جہاں زخم کا نشان نہ ہو.پھر آپ کی ہچکی بندھ گئی اور آپ نے سسکیاں بھرتے ہوئے فرمایا میری بدقسمتی کہ میں اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہوا اور بجائے میدان جنگ میں شہید ہو نے کے میں اب چارپائی پر مررہا ہوں(اسد الغابۃ خالد بن الولید).یہ کتنا عظیم الشان نشان تھا جو
Page 52
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو دیا گیا.آپ کے شدید ترین دشمن آپ پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے اتنی شاندار قربانیاں کیں کہ دنیا میں اس قسم کی کوئی مثال نہیں مل سکتی.اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے پلوٹھوں کو مارا اور اس طرح مارا کہ انہیں آپ سے کوئی محبت نہیں تھی.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بیٹوں کو اس نے ایمان اور محبت کے ساتھ مارا اور ایسا مارا کہ مرتے ہوئے بھی اگر ان کو کچھ حسرت تھی تو یہی کہ وہ چارپائی پر کیوں مر رہے ہیں میدان جنگ میں لڑتے ہوئے انہیں شہادت کیوں نصیب نہ ہوئی.عمر و بن عاصی جوبعد میں عمرو بن عاص کہلائے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے بیٹے نے جو آپ سے پہلے مسلما ن ہو گئے تھے اور بڑے عظیم الشان صحابیؓ تھے دیکھا کہ وہ تڑپ رہے ہیں.بیٹے نے کہا باپ آپ کیوں اتنا تڑپتے ہیں خدا تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ آپ کو ایمان نصیب ہوا.عمرو بن عاص نے آہ بھری اور کہا میرے بیٹے ایمان سے پہلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا شدید دشمن تھا کہ آپ کی شکل دیکھنے کو بھی میں برا سمجھتا تھا.اگر آپ میرے پاس سے گذرتے تو میں اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا تھا، تا نعوذ باللہ آپ کی منحوس شکل نظر نہ آئے.اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان بخشا مگر اس وقت مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی کہ شدتِ محبت کی وجہ سے میں نے آپ کی شکل کو نہیں دیکھا میں ہمیشہ اپنی نظریں نیچی رکھتا تھا گویاکفر کی حالت میں بُغض کی وجہ سے میں نے آپ کی شکل کو نہیں دیکھا اور ایمان کی حالت میں شدت محبت کی وجہ سے میں نے آپ کی شکل کو نہیں دیکھا.چنانچہ آج اگر کوئی شخص مجھ سے آپ کا حلیہ پو چھے تو میں نہیں بتا سکتا میرے بیٹے! بے شک خدا تعالیٰ نے مجھے بہت سی نیکیوں کی تو فیق دی ہے لیکن آپ کی وفات کے بعد جھگڑے ہو تے رہے اور بعض غلطیاں بھی ہم سے ہوئیں نہ معلوم اب میں کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو شکل دکھاؤں گا(مسلم کتاب الفتن باب کون الاسلام یـھدم ما قبلہ).دیکھو یہ کتنے بڑے دشمن تھے جو دن اور رات آپ کی دشمنی کرتے تھےمگر بعد میں انہیں ایسا ایمان نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو محبت کی چھری سے ذبح کر لیا.پھر ابوجہل کو دیکھو.وہ کتنا بڑا دشمن تھا اس کا بیٹا عکرمہ ؓ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور پھر اس نے جو قربانی صحابہؓ کو بچا نے کے لئے کی وہ بھی ایسی شاندار ہے جس کی نظیر دنیامیں نہیں ملتی.آپ صحابہؓ کی جانوں کو بچانے کے لئے ایک ایسے لشکرمیں گھس گئے جس کی تین لاکھ سے دس لاکھ تک تعداد بتائی جاتی ہے قلب لشکر میں جاتے ہی آپ نے کمانڈر انچیف کو زخمی کیا اور حملہ کر کے قلب لشکر میں انتشار پیدا کر دیا اور پھر وہیں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے.
Page 53
ابو سفیان تو آپ کی زندگی میں ہی آپ کا شکا ر ہو گیا تھا.پھر اسی کا بیٹا معاویہؓ تھا جو اسلام کا ایک پہلوان ہوا.بے شک ان سے بعض غلطیاں بھی ہوئیں مگر انہوں نے اسلام کی نہایت شاندار خدمت سر انجام د ی ہے.غر ض حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے تو صرف پلوٹھے مرے مگر یہاں دشمن کی ساری اولادیں مر گئیں.وہ آپ پر ایمان لے آئیں اور اپنے باپوں سے کٹ کر روحانی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں شا مل ہو گئیں.سولھویں فضیلت (۱۶) پھر قحط کا نشان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا.حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پر ایک سال کا قحط آیا.ٹڈی آئی اور فصلوں کو کھا گئی.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر سات سال کا قحط پڑا.آخر انہوں نےآپؐ سے دعائیں کروائیں تب اس عذاب سے انہیں نجات حاصل ہوئی(بخاری کتاب التفسیر سورۃ الدخان باب قولہ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا.....).سترھویں فضیلت (۱۷) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھی مگر جیسا کہ قرآن کریم اور تورات دونوں سے معلوم ہو تا ہے آپ اسے برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دَنَا فَتَدَلّٰى.فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى (النجم:۹،۱۰ ) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تڑپ پیدا ہوئی اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف اس کی ملاقات کے لئے صعود شروع کیا ادھر خدا تعالیٰ کے دل میں آپ کی وہ محبت موجزن تھی کہ وہ خود نیچے اتر آیا تاکہ ملاقات میں دیر نہ ہو.پھر وہ دونوں مل کر ویسے ہی نہیں آگئے بلکہ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى.عرب میں یہ رواج تھا کہ جب دوآدمیوں میں پیار او رمحبت ہو جاتی تھی تو وہ ایک ہی کمان سے تیر چلاتے تھے اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جدھر اس کا تیر جائےگا ادھر ہی میرا تیر جائے گا اور جدھر میرا تیر جائے گا ادھر ہی اس کا تیر جائے گا(معالم التنزیل زیر آیت فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ).اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے معاہدہ کیاکہ اے محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) آج سے جدھر تمہارا تیر چلے گا ادھر ہی میرا تیر چلےگا.اور جدھر میرا تیر چلے گا ادھر ہی تیرا تیر چلے گا.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ادھر ہی تیر چلایا جدھر خدا تعالیٰ نے تیر چلایا.خواہ آپ کا وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور خدا تعالیٰ کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سےا تنا پیار تھا کہ اس نے بھی ادھر ہی تیر چلایا جدھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلایا مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى(الانفال:۱۸) میںبھی اسی طرف اشارہ ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) جب تو نے دشمنوں کی طرف کنکروں کی مٹھی پھینکی تو وہ کنکر تو نے نہیں پھینکے ہم نے پھینکے تھے کیونکہ ہمارا تم سے یہ وعدہ تھا کہ جدھر تمہارا تیر
Page 54
چلے گا ادھر ہی ہمارا تیر چلے گا.یہ تو دشمن کےمقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا سلوک تھا.اب دوستی کا حال دیکھو خدا تعالیٰ فرماتا ہے یَدُ اللّٰہِ فَوْقَ اَیْدِیْھِمْ (الفتح:۱۱) تیری بیعت کرنے والوں اور تیری غلامی میں شامل ہو نے والوں پر ہمارا ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے تیرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے.غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دونوں ایک ہو گئے تھے اس طرح کہ اگر تیر چلتا تھا تو دونوں کا ایک طرف چلتا تھا اور اگر کسی طرف نگاہِ لطف اٹھتی تھی تودونوں کی اسی طرف اٹھتی تھی.یہ کتنی بڑی تجلی ہے جواللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی.اس کے مقابلہ میں موسوی تجلی کیا حقیقت رکھتی ہے.اٹھارھویں فضیلت (۱۸)حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف کتاب ملی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کے علاوہ کلام اللہ بھی دیا گیا اور ان دونوںمیں بڑا بھاری فرق ہے.کتاب کے معنے حکم کے ہو تے ہیں اوراسے دوسرے الفاظ میں بھی تبدیل کیاجا سکتا ہے لیکن کلام اللہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا.گویا کتاب کے مفہوم میں الفاظ کی شرط نہیں مگر کلام اللہ میں الفاظ کی شرط ہے.شاہان عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ بڑے بڑے ادیبوں کو وزیر مقرر کیا کرتے تھے.ایک بادشاہ کا وزیر بات کرتے وقت ہکلاتا تھا اور وہ ’’ر‘‘ نہیں بو ل سکتا تھا جیسے بعض بچے ’’ر‘‘ کی جگہ ’’ل‘‘ بول دیتے ہیں مثلاً ’’میری کتاب‘‘ کہنا ہو تو وہ کہیں گے ’’میلی کتاب‘‘ اسی طرح وہ وزیر بھی ’’ر‘‘ کی بجائے ’’ل‘‘ بولتا تھا.کسی نے بادشاہ کو طعنہ دیا کہ تو نے بڑا ادیب رکھا ہوا ہے اس کی تو زبان میں نقص ہے اگر کوئی بادشاہ تمہارے پاس آگیا تو تمہاری ذلت ہو گی.بادشاہ نے کہا مجھے تو ابھی تک محسوس نہیں ہوا کہ میرا وزیر یہ نقص اپنے اندر رکھتا ہے.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہروقت میرے پاس رہے اور مجھے اس کے اس نقص کا علم نہ ہو.اس شخص نے کہا میں اس کا ثبوت بہم پہنچا دیتا ہوں آپ اسے ’’ر‘‘ والے الفاظ لکھوا کر دیکھ لیں.بادشاہ نے وزیر کا امتحان لینے کے لئے ایک فقرہ بنایا اور اسے بلایا.اس وقت یہ دستور تھا کہ بادشاہ وزراء کو آرڈر دیتے تھے اور وزیر آگے آرڈر دیا کرتا تھا.اگر کاتب کو کوئی چیز لکھوانی ہوتی تھی تو بادشاہ بولتا جاتا تھااور وزیر آگے کاتب کو لکھواتا جاتا تھا.کاتب کی یہ شان نہیں ہو تی تھی کہ وہ بادشاہ سے براہ راست مخاطب ہو بادشاہ نے کہا لکھو اَمَرَ اَمِیْـرُ الْاُمَرَآءِ اَنْ یُّـحْفَـرَ الْبِئْـرُ فِی الطَّرِیْقِ لِیَشْـرَبَ مِنْہُ الْمَآءَ الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ یعنی بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں راستہ میں ایک کنواں کھو دا جائے تاکہ شہر سے باہر جانے والے اور شہرکی طرف آنے والے سب لوگ اس سے پانی پی سکیں.اس فقرہ میں اس نے سب ’’ر‘‘ والے الفاظ جمع کر دیئے بادشاہ سے سن کر وزیر نے فوراً یہ حکم اس طرح لکھوانا شروع کیا
Page 55
شاہان عرب میں یہ رواج تھا کہ وہ بڑے بڑے ادیبوں کو وزیر مقرر کیا کرتے تھے.ایک بادشاہ کا وزیر بات کرتے وقت ہکلاتا تھا اور وہ ’’ر‘‘ نہیں بو ل سکتا تھا جیسے بعض بچے ’’ر‘‘ کی جگہ ’’ل‘‘ بول دیتے ہیں مثلاً ’’میری کتاب‘‘ کہنا ہو تو وہ کہیں گے ’’میلی کتاب‘‘ اسی طرح وہ وزیر بھی ’’ر‘‘ کی بجائے ’’ل‘‘ بولتا تھا.کسی نے بادشاہ کو طعنہ دیا کہ تو نے بڑا ادیب رکھا ہوا ہے اس کی تو زبان میں نقص ہے اگر کوئی بادشاہ تمہارے پاس آگیا تو تمہاری ذلت ہو گی.بادشاہ نے کہا مجھے تو ابھی تک محسوس نہیں ہوا کہ میرا وزیر یہ نقص اپنے اندر رکھتا ہے.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہروقت میرے پاس رہے اور مجھے اس کے اس نقص کا علم نہ ہو.اس شخص نے کہا میں اس کا ثبوت بہم پہنچا دیتا ہوں آپ اسے ’’ر‘‘ والے الفاظ لکھوا کر دیکھ لیں.بادشاہ نے وزیر کا امتحان لینے کے لئے ایک فقرہ بنایا اور اسے بلایا.اس وقت یہ دستور تھا کہ بادشاہ وزراء کو آرڈر دیتے تھے اور وزیر آگے آرڈر دیا کرتا تھا.اگر کاتب کو کوئی چیز لکھوانی ہوتی تھی تو بادشاہ بولتا جاتا تھااور وزیر آگے کاتب کو لکھواتا جاتا تھا.کاتب کی یہ شان نہیں ہو تی تھی کہ وہ بادشاہ سے براہ راست مخاطب ہو بادشاہ نے کہا لکھو اَمَرَ اَمِیْـرُ الْاُمَرَآءِ اَنْ یُّـحْفَـرَ الْبِئْـرُ فِی الطَّرِیْقِ لِیَشْـرَبَ مِنْہُ الْمَآءَ الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ یعنی بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں راستہ میں ایک کنواں کھو دا جائے تاکہ شہر سے باہر جانے والے اور شہرکی طرف آنے والے سب لوگ اس سے پانی پی سکیں.اس فقرہ میں اس نے سب ’’ر‘‘ والے الفاظ جمع کر دیئے بادشاہ سے سن کر وزیر نے فوراً یہ حکم اس طرح لکھوانا شروع کیا حَکَمَ حَاکِمُ الْـحُکَّامِ اَنْ یُّقْلَبَ الْقَلِیْبُ فِی السَّبِیْلِ لِیَنْتَفِعَ مِنْہُ الصَّادِیْ وَالْبَادِیْ.بادشاہ سخت حیران ہوا شکایت کرنے والا بھی پاس کھڑا تھا اس نے کہا دیکھا یہ ’’ر‘‘ نہیں بول سکتا.بادشاہ نے کہا مجھے تو وزیر کے کسی نقص کا پتہ نہیں لگا اس کے کمال کا پتہ لگا ہے.مجھے تو حیرت ہے کہ کتنی جلدی اس نے میرے حکم کو دوسرے الفاظ میں بدل دیا جس کے بعینہٖ وہی معنے ہیں میں ایسا قابل آدمی نہیں چھوڑ سکتا پس حکم کے الفاظ کو سننے والا بدل سکتا ہے اور اس میں غلطیاں بھی ہوسکتی ہیں جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں حدیث باللفظ ہے اور فلاں حدیث بالمعنیٰ.محدث کہتے ہیں کہ حدیث باللفظ وہ ہوتی ہے جس میں بعینہٖ وہی الفاظ ہوں جو دوسرے سے سنے ہوں.مثلاً ایک روایت کو شام والوں نے بھی بیان کیا ہو، بخارا والوں نے بھی بیان کیا ہو، مصر والوں نے بھی بیان کیا ہو اور اس کے الفاظ ایک ہی ہوں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے ہیں تو یہ روایت باللفظ ہو گی.ایسی حدیثیں عموماً چھوٹی چھوٹی ہو تی ہیں جن کا یاد رکھنا آسان ہو تا ہے یا ان میں وزن ہو تا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں.مثلاً ایک حدیث ہے کَلِمَتَانِ خَفِیْفَتَانِ عَلَی اللِّسَانِ ثَقِیْلَتَانِ فِی الْمِیْـزَانِ حَبِیْبَتَانِ اِلَی الرَّحْـمٰنِ سُـبْحَانَ اللہِ وَبِـحَمْدِہٖ سُبـْحَانَ اللہِ الْعَظِیْمِ.(بخاری کتاب الایمان والنذور باب اذا قال واللہ لا اتکلم الیوم....) یعنی دو کلمےایسے ہیں جن کا زبان سے ادا کرنا بہت آسان ہے مگر میزان میں وہ بہت بھاری ہیں اور خدائے رحمان کو بہت محبوب ہیں.وہ کلمے یہ ہیں سُـبْحَانَ اللہِ وَبِـحَمْدِہٖ سُبـْحَانَ اللہِ الْعَظِیْمِ.اس حدیث کاوزن ایسا ہے کہ دماغ پر بغیر کسی قسم کا بوجھ ڈالنے کے یاد ہوجاتی ہے.پس مختلف راویوں سے جو روایت ایک ہی الفاظ میں پہنچی ہو اسے روایت باللفظ کہتے ہیں اور روایت بالمعنیٰ وہ ہوتی ہے جس کو بیان کرتے وقت راوی نے اپنے الفاظ استعمال کئے ہوں.غرض موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی جس کے معنے حکم کے ہو تے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیئے جن میں سے آپ کو کچھ احکام تو لفظاً لفظاً یاد رہ گئے اور باقی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور وہ تورات میں درج ہو گئے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام اللہ دیا گیا جس کے الفاظ اوّل سے آخر تک وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں.گویا سورۃ فاتحہ کی ’’ب‘‘ سے لے کر سورۃ النّاس کی ’’س‘‘ تک نہ کوئی لفظ ایسا ہے اور نہ کوئی زیر اور زبر جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے شامل کر دیا ہو.بلکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں.یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنی بڑی فضیلت ہے کوئی عیسائی یا یہودی تورات کے متعلق قسم نہیںکھا سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی.کوئی عیسائی یا یہودی بھلا یہ قسم کھا کر کہہ تو دے کہ میرے بیوی بچو ں کو خدا تعالیٰ تباہ کرے اور اگلے جہان میں بھی ان پر لعنت ہو اگر تورات کے الفاظ وہی نہ ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترے تھے.کوئی عیسائی یا یہودی ایسی قسم نہیں کھا سکتا.لیکن ہم قرآن کریم کے متعلق یہ قسم کھاکر کہہ سکتے ہیں آج بھی اور آئندہ بھی کہ اگر یہ وہی الفاظ نہ ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے تو ہمارے بیوی بچوں کو خدا تعالیٰ تباہ کرے اور اگلے جہان میں بھی ان پر لعنت ہو.یہ کتنی بڑی فضیلت ہےجو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہوئی.
Page 56
یہودی بھلا یہ قسم کھا کر کہہ تو دے کہ میرے بیوی بچو ں کو خدا تعالیٰ تباہ کرے اور اگلے جہان میں بھی ان پر لعنت ہو اگر تورات کے الفاظ وہی نہ ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترے تھے.کوئی عیسائی یا یہودی ایسی قسم نہیں کھا سکتا.لیکن ہم قرآن کریم کے متعلق یہ قسم کھاکر کہہ سکتے ہیں آج بھی اور آئندہ بھی کہ اگر یہ وہی الفاظ نہ ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے تو ہمارے بیوی بچوں کو خدا تعالیٰ تباہ کرے اور اگلے جہان میں بھی ان پر لعنت ہو.یہ کتنی بڑی فضیلت ہےجو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حاصل ہوئی.(۲)علاوہ مذکورہ بالا معجزات و کرامات کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف قرآن کریم اور بائیبل میں منسوب کی گئی ہیں اور جن میں مقابلہ کر کے ہم نے بتایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ تھا.ایک اور ذریعہ مقابلہ کا بھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملتا ہے.حضرت ابراہیمؑ کی آنحضرتؐکے متعلق دعا سورۂ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر آتا ہے جو انہوں نے بنو اسمٰعیل کے موعود نبی کی نسبت کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں.رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.(البقرۃ:۱۳۰) اے ہمارے رب تو ان لوگوں میں اپنا ایک رسول مبعوث فرماجو ان پر تیری آیا ت کی تلاوت کرے.انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ نفوس کرے تو بڑا غالب اور حکمت والا خدا ہے.حضرت ابراہیمؑ کی دعا اور کوثر کا تعلق یہ دعا جو سورۂ بقرہ میں آئی ہے اس میں درحقیقت انبیاء کے فرائض اور ان کے مخصوص کام کا ذکر ہے اور سورۂ کو ثر میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے نہ صرف یہ کہ ابراہیمؑ کی یہ دعا پو ری ہوئی بلکہ انتہائی کمال یا کوثر ان صفات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا.اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تلاوتِ آیات کی، نہ صرف تعلیمِ کتاب کی، نہ صرف تعلیمِ حکمت کی، نہ صرف تزکیۂ قوم کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں صفات میں آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے اور اس طرح تمام انبیاء سابقین پر آپ کو فضیلت عطا فرما دی گئی ہے.میرے نزدیک قرآن کریم کی بعض آیات دوسری آیا ت کے لئے بطور کنجی ہو تی ہیں جن سے سارامضمون نکل آتا ہے جس طرح تمام صورتوں کی ایک مشترک کنجی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ہے اسی طرح ہر سورۃ میں
Page 57
ایک ایک آیت اس سورۃ کے لئے بطور کنجی ہے جس سے تمام سورۃ کو حل کیا جا سکتا ہے.میں ابھی نو جوان ہی تھا کہ بعض دوستوں نے مجھ سے خواہش کی کہ میں انہیں قرآن کریم پڑھاؤں ہم نے سورۂ بقرہ شروع کی.پڑھاتے پڑھاتے میرے دل میں ڈالا گیا کہ سورۂ بقرہ کی کنجی یہ آیت ہے کہ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.پھرمیں نے اس آیت کے مضمون کو ساری سورۃ پر چسپاں کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعہ میں ساری سورۃ اسی آیت کے گرد چکر کھاتی ہے.اب مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کھولا ہے کہ سورۂ کوثر اس دعائے ابراہیمی کا جواب ہے جس کاسورۂ بقرہ میں ذکر آتا ہے اور اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ وہ وعدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے کیا تھا وہ نہ صرف پو را ہوگیا ہے بلکہ ہم نے ہر صفت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے.دعائے ابراہیمی یہ تھی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.اے ہمارے رب ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو مکہ والوں میں اپنا ایک نبی اور رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو غیر قوم میں سے نہ ہو.رَسُوْلًا کا لفظ بتاتا ہے کہ دعا آئندہ زمانہ کے متعلق تھی.کیونکہ جب یہ دعا کی گئی تھی اس وقت دو رسول تو موجود تھے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام دونوں نبی تھے ان کا اپنی موجود گی میں یہ دعا کرنا کہ اے خدا تو ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما تبھی درست ہو سکتا ہے جب یہ دعا آئندہ زمانہ کے متعلق ہو.ورنہ ایک چیز کے ہو تے ہوئے یہ کہنا کہ اے اللہ تو ہمیں وہ چیز دے عجیب بات معلوم ہو تی ہے اور یا پھر یہ دعا کی جاتی کہ رُسُلًا مِّنْھُمْ تب بھی ہم کہہ سکتےتھے کہ پے در پے رسول آنے کی دعاہے.مگر اس آیت میں رُسُلًا مِّنْھُمْ نہیں کہا رَسُوْلًا مِّنْهُمْ کہا ہے جس سے آئندہ زمانہ میں کسی خاص رسول کی طرف اشارہ مقصود ہے.چنانچہ اس جگہ رَسُوْلًا کی تنوین تعظیم کے لئے ہے پس رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ کہ یہ معنے ہوں گے کہ اے ہمارے رب تو اسمٰعیل (علیہ السلام) کی نسل میں سے عظیم الشان رسول مبعوث فرما.مِنْهُمْ جو انہی میں سے ہو.تیرے وعدے بنو اسحاق سے بھی ہیں مگر بنو اسمٰعیل کو بھی فراموش نہ کر دینا بلکہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجئو جس کے کام یہ ہو ں کہ (۱)يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وہ ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے(۲)وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ اور وہ ان کو ایک کامل کتاب سکھائے (۳) وَ الْحِكْمَةَ اوراحکام کی اغراض اور فلسفہ سکھائے (۴) وَيُزَكِّيْهِمْ اور ان کے دلوں کو پاک کرے اور دنیوی ترقی کے راستے بتائے اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ تو بڑا غالب اورحکمتوں والا خدا ہے اور اس غلبہ اور حکمت کے ماتحت تجھ سے ایسی التجا کرنا کوئی بڑی بات نہیں.
Page 58
یہ دعا سورۂ بقرہ کے پندرھویں رکوع میں آتی ہے.اس کے بعد اسی سورۃ کے اٹھارویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.كَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ.یعنی ہم نے تمہارے اندر وہ رسول بھیج دیا ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور آگے وہی باتیں بیان کی ہیں جو دعائے ابراہیمی میں بیان کی گئی تھیں وہاں کہا تھا يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَوہ ان کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے.یہاں فرمایا يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وہ تم کو ہماری آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے وہاں فرمایا تھا يُزَكِّيْهِمْ وہ ان کے دلوں کوپاک کرے یہاں فرماتا ہے يُزَكِّيْكُمْ وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہےوہاں فرمایا تھا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وہ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے.یہاں فرماتا ہے يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وہ تم کو کتاب اور حکمت سکھاتاہے.غرض جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے مانگی تھیں وہ سب کی سب یہاں بیان کر دی ہیں جس سے صاف طور پر اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نےجو دعا کی وہ خدا تعالیٰ نے سن لی.گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہوا کہ وہ دعائے ابراہیمی کے پورا کر نے والے ہیں اور دعا میں چار باتیں کہی گئی تھیں (۱)تلاوتِ آیات (۲) تعلیمِ کتاب(۳) تعلیمِ حکمت (۴) تزکیۂ نفوس.گویا آپ کی بعثت کی غرض یہ چار عظیم الشان کام تھے.مگر ظاہر ہے کہ دنیا میں جو نبی بھی آئے گا وہ یہی چاروں کام کرے گا.ان کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی کیا ہو سکتا ہے.پس محض اتنی بات سے آپ کو کوثر کا ملنا ثابت نہیں ہو سکتا.آپ کو کوثر کا ملنا تب ثابت ہو سکتاہے جب ہر کام میں آپ کو ایسا نمایا ں مقا م حاصل ہو کہ دوسرے انبیاء میں اس کی مثال تلاش کرنے سے بھی نہ مل سکتی ہو.اگر آپ نے لوگوں کو آیات پڑھ کر سنا دیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وعدہ پورا ہو گیا.لیکن اگر آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر آیات سنائی ہیں تو پھر بےشک یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو کوثر ملا.اسی طرح اگر آپ نے کتاب سکھائی تو ابراہیمی دعا پوری ہوگئی لیکن اگر آپ نے ایسی کتاب سکھائی کہ دوسرے انبیاءمیں اس کی مثال نہیں ملتی تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہو گی کہ آپ کو کوثر ملا.پھر اگر آپ نے حکمت سکھائی تو حکمت سکھا نےسے وعدہ ابراہیمی تو پورا ہو گیا لیکن اگر آپ نے حکمت سکھائی اور اتنی سکھائی کہ دوسرے انبیاء میں سے کسی نبی نے نہیں سکھائی تو یہ آپ کو کوثرملا.پھر اگر آپ يُزَكِّيْهِمْ کے مطابق تزکیۂ نفوس کر دیتےتو وعدۂ ابراہیمی پورا ہو جاتا.لیکن اگر آپ ایسا تزکیہ کریں کہ اس کی دنیا میں کوئی مثال
Page 59
نہ ملے تو یہ ثبوت ہو گا اس بات کا کہ آپ کو کوثر ملا.پس کوثر کے یہ معنے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اور جو وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا وہ نہ صرف ہم نے پورا کر دیا ہے بلکہ اپنے پاس سے زائد بھی دیا ہے اور اس قدر دیا ہے کہ کسی اور نبی میں اس کی مثال نہیں مل سکتی.غرض سورۂ بقرہ رکوع ۱۵ میں جس دعا کا ذکر کیا گیا تھا چونکہ اس دعا کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم مبعوث ہوئے تھے اس لئے یہاں سورۃ کوثر میں جہاں قرآن کریم اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے.بتایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کیا وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں وہ ہم نے پوری کر دیں یا نہیں اور کیا وہ چیزیں جو دعا میں مانگی گئی تھیں ہم نے تجھے وہ اتنی نہیں دیں کہ کسی اورنبی کو اتنی نہیں ملیں.دعائے ابراہیمی چونکہ ایک اہم دعا ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں مختلف رنگوں میں اس دعا کے پورا ہو نے کا ذکر فرمایا ہے.سورۃ آل عمران رکوع ۱۷ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ١ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.(اٰلِ عـمران:۱۶۵) اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑااحسان کیا جبکہ اس نے ان کی قوم میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے.ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، قوم کو ترقی کے ذرائع بتلاتا ہے، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس سے پہلے نہایت خطرناک گمراہی میں مبتلا تھے اس جگہ پھر وہی چاروں چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا دعائے ابراہیمی میں ذکر آتا تھا.پھر سورۂ جمعہ رکوع۱ میں فرماتا ہے.هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ١ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.(الـجمعۃ:۳) وہ خد اہی ہے جس نے اس قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور وہ اس سے پہلےبڑی گمراہی میں مبتلا تھے.اسی طرح قرآن کریم میں بعض اور مقامات پر بھی اس دعا کے ٹکڑوں کو بیان کیا گیا ہے.سورۂ نساء ع ۸ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَاۤ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ١ۚ فَقَدْ اٰتَيْنَاۤ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ
Page 60
وَاٰتَيْنٰهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا.(النسآء:۵۵) فرمایاکیا یہود اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ مکہ والوں کو بھی ہم نے اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا ہے.بےشک بنواسحاق بھی ابراہیم کی اولاد ہیں اور ان پر بھی ہم نے بڑے بڑے فضل کئے ہیں مگر مکہ والے بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیںکیا خدا تعالیٰ ان پر فضل نازل نہ کرتا.یہود کو تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے خاندان کو عزت بخشی ہے.مگر یہ لوگ بجائے خوش ہو نے کے مکہ والوں پر حسد کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیوں نوازا ہے.انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے آلِ ابراہیم کو کیا کیا دیا تھا اور یہ بھی اس آل کا ہی ایک ٹکڑا ہے.جس طرح انہیں حکومت ملی تھی انہیں بھی ملنی چاہیے تھی اور اب جبکہ ہم ان کو بھی اپنے فضل سے حصہ دینے لگے ہیں ان کو غصہ کیوں آرہا ہے.اس بات کا ثبوت کہ اس آیت میں بنو اسماعیل کا ہی ذکر ہے پہلی آیات سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اسی رکوع میں فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ وَ يَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا.(النسآء:۵۲) تو دیکھ تو سہی ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب میں سے ایک حصہ دیا ہے وہ لغو باتوں اور شیطانی تعلیموں کو مانتے ہیںاور وہ کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں حالانکہ وہ مشرک ہیں اور مومن مؤحّد.اس کے بعد فرماتا ہے اگر بنو اسماعیل کو خدا تعالیٰ کے فضل سے کچھ مل گیا تھا تو انہیں تو خوش ہو نا چاہیے تھا کہ ان کے خاندان کی عزت ہو گئی نہ کہ ان کے دلوں میں غصہ پید اہو جاتا.پھر سورۂ نساءرکوع ۱۷ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ١ؕ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.(النسآء:۱۱۴) اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو اس سے پہلے تو نہیں جانتاتھا اور تجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اس میں بھی کتاب اور حکمت کے نزول کا ذکر کیا گیا ہے.پھر سورۂ احزاب ع۴ میں اہلِ بیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا.(الاحزاب:۳۵) اے اہل بیت جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھایا جاتا ہے اس کو یاد رکھو.
Page 61
یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور خبر رکھنے والا ہے.سورۃ لقمان ع ۱ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.تِلْکَ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ الْحَکِیْمِ.(لقمان:۳) یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں.سورۂ آل عمرا ن ع ۶ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذٰلِکَ نَتْلُوْہُ عَلَیْکَ مِنَ الْاٰیٰتِ وَ الذِّکْرِ الْحَکِیْمِ.( اٰلِ عـمران:۵۹) ہم تجھے اپنی آیات اور حکمت والا ذکر پڑھ کر سناتے ہیں.پھر سورۂ یونس ع۱ میں فرماتا ہے تِلْکَ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ الْحَکِیْمِ.(یونس:۲) یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں.اسی طرح سورۃ یٰسٓ ع۱ میں آتا ہے.وَالْقُرْاٰنِ الْحَکِیْمِ.(یٰسٓ : ۳) قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے.آنحضرت صلعم کی بعثت کی چار اغراض اور آنحضرت کے لئے اس میں کوثر کا ہونا اوپر کی آیتوں سے واضح ہے کہ قرآن کریم میں بار بار یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ آپؐکی بعثت کی چار غرضیں تھیں.(۱) تلاوتِ آیات (۲) تعلیمِ کتاب (۳) تعلیمِ حکمت اور (۴) تزکیۂ قوم.اور پھر متواتر قرآنی آیات نے بتایا ہے کہ یہ کام آپ نے پورا کر دیا جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں تمام نبیوں کا اپنے اپنے رنگ میں یہی کام ہو تا ہے.اس جگہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا آپ کو ان چاروں صفات میں کوثر بھی عطا ہوا ہے یا نہیں.اٰيٰتِكَ میں خدا تعالیٰ کی طرف راہنمائی کرنے والے عقلی امور اور معجزات کی طرف اشارہ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ میں اٰيٰتِكَ سے دو طرف اشارہ ہو سکتا ہے (۱)ان عقلی امور کی طرف جو خدا تعالیٰ کی طرف یا اس کی صفات کی طرف راہنمائی کر نے والے ہیں (۲) ان معجزات کی طرف جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے پاک بندوں کی شان نمایاںکر نے کے لئے ظاہر ہو تے ہیں.میرے نزدیک یہ دونوںچیزیںاس آیت میںشامل ہیں یعنی وہ دلائل عقلیہ جو خدا تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور وہ معجزات و نشانات جو خدا تعالیٰ کی
Page 62
طرف سے ظاہرہو تے ہیںوہ بھی اس میں شامل ہیں.دین کی معرفت کے لئےمندرجہ ذیل اہم امور کا علم ضروری ہے:.دین کی معرفت کے لئے ضروری امور (۱) ثبوت ہستی باری تعالیٰ.جب مذہب کی بنیادہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے تو ہر مذہب کا فرض ہے کہ وہ ایسےثبوت دے جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر انسان کا یقین بڑھے یعنی یہ بتایا جائے کہ کیا خدا موجود ہے؟ اوراگر ہے تواس کے وجود کے دلائل کیا ہیں؟ (۲) اس کی صفات کی صحیح تشریح اور ان کا باہمی تعاون.اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ خدا تعالیٰ کے اندر مختلف صفات پائی جاتی ہیں تو اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیںہو سکتا.مگر یہ کہ خدا تعالیٰ کیا کیا صفات رکھتا ہے اور ان کا ثبوت کیا ہےیہ اور چیز ہے اور مذہب کافرض ہے کہ وہ اس پہلو پر بھی روشنی ڈالے.(۳) ملائکہ(۴)انبیاء(۵)قضاء و قدر (۶) بعث بعد الموت.اگر صفات ِ الٰہیہ کو شِق کے طور پرلیںتویہ پانچ چیزیں بن جاتی ہیں اور اگر علیحدہ لیا جائے تو یہ چھ باتیں بن جاتی ہیں.بہر حال بڑی بڑی باتیں یہی ہیں ان امور کے متعلق جو تعلیم اسلام میں پائی جاتی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی اور یہ اسلام کو دوسرےمذاہب پر ایک نمایاں فوقیت حاصل ہے.ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت سب سے پہلی اور بڑی چیز ہستی باری تعالیٰ ہے اس کے متعلق میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دوسری کتابوں میں خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں.مذہب کی تو بنیاد ہی خدا تعالیٰ پر ہے جب خدا تعالیٰ کا ذکر ہی کسی مذہب میں نہ ہو تو وہ مذہب قائم نہیں رہ سکتا.بائبل، ژند اوستااور وید وغیرہ کتابوں کو اگر ہم الہامی کتب تسلیم کرتے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ ان میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہو.پس یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ دوسری مذہبی کتب میں خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں.دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آیا انہوں نے خدا تعالیٰ کی ہستی کے دلائل بھی پیش کئے ہیں یا نہیں.ورنہ محض خدا تعالیٰ کا نام لے دینے سے لوگوں کو یہ یقین نہیں آسکتا کہ خدا تعالیٰ فی الواقعہ موجود بھی ہےاور اس میں کئی قسم کی صفات بھی پائی جاتی ہیں اس کے لئے مختلف دلائل کی ضرورت ہو تی ہے جن کا مہیا کرنا خود الہامی کتاب کے ذمہ ہوتا ہے.مگر ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت سوائے قرآن کریم کے اور کسی الہامی کتاب نے پیش نہیں کئے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کسی ہندو سے پوچھو تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں دے گا.عیسائی سے پوچھو تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے وجود کا کچھ نہ کچھ ثبوت دے گا مگر سوال یہ ہے کہ وہ دلیلیں آیا ان کی الہامی کتب کی ہیں؟ وہ صاف کہہ دیں گے کہ یہ دلائل ہماری کتاب نے تو نہیں دیئے ہم خود پیش کر رہے ہیں.گویا ان کا اپنے پاس سے ان امور
Page 63
کے دلائل دینا ثابت کرتا ہے کہ ان کے پیرؤوں نے خدا تعالیٰ کو کوثر دیا ہے نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے ان کو کوثر دیا ہے.لیکن قرآن کریم جب بھی کوئی بات پیش کرتا ہے ساتھ ہی اس کے دلائل بھی دیتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو قرآن کریم اور دوسری کتب میں ہے.قرآن کریم صرف خدا تعالیٰ کے وجود کو ہی پیش نہیں کرتا بلکہ بنی نوع انسان کو اس کی ہستی کے دلائل بھی دیتا ہے اور ایسے ثبوت پیش کرتا ہے جن کا انکار کوئی سلیم الفطرت انسان نہیں کر سکتا لیکن دوسری کتب میں ہستی باری تعالیٰ پر کوئی دلیل نہیں.اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں.صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا رب رحیم ہے، دیالوہے، کرپالوہے.خدا تعالیٰ کی صفات کا حقیقی نقشہ نہیں کہلاسکتا.یہ تو محض دنیوی خیالات کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے اگر سن لیا کہ لوگ سخی کو اچھا سمجھتے ہیں تو کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ دیا لو ہے.اگر سن لیا کہ لوگ حسن سلوک کو اچھا جانتے ہیں تو کہہ دیا خدا تعالیٰ کرپالو ہے.اصل چیز تو یہ ہے کہ صفاتِ الٰہیہ کی صحیح تشریح کی جائے اور ان کا باہمی تعلق واضح کیا جائے.مثلاً تورات میں خدا تعالیٰ یہ تو کہتا ہے کہ میں سزا دوں گا مگر وہ کیوں سزا دیتا ہے اس کے متعلق تورات خاموش ہے اور پھر اگر وہ سزا دیتا ہے تو رحم کرنے والا کیسے ہوا؟ اور اگر رحم کرتا ہے تو پھر سزا دینے والا کیسے ہوا؟ ان دونوں صفات کا باہمی ربط کیا ہے؟ اس کے متعلق وہ بالکل خاموش ہے.یہ صرف قرآن کریم ہی ہے جس نے ہمیں تفصیل کے ساتھ صفاتِ الٰہیہ کا علم دیا ہے اور تفصیل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ہستی کے دلائل دیئے ہیں.میں دوسرے مذاہب والوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کے وجود کی کوئی ایک دلیل ہی اپنی کتاب سےنکال دیں مگر وہ ایسا کبھی نہیں کر سکیں گے اور اگر ان کے ماننے والے اپنے پاس سے خدا تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں دیتے ہیں خود کتاب کوئی دلیل نہیں دیتی تو یہ بندوں کا خدا تعالیٰ پر احسان ہوا.نہ کہ خدا تعالیٰ کا بندوں پر احسان.ملائکۃ اللہ (۲) ملائکہ کو لو تو دوسری کتابوں میں ملائکہ کا ذکر بے شک آتا ہے مگر یہ کہ ان کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بنائے ہیں.ان کا اور خدا تعالیٰ کا اور ان کا اور بندوں کا تعلق کیسا ہے؟ ان سوالات پر ان کتب نے کوئی روشنی نہیں ڈالی.لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو صرف ملائکہ پر ایمان لانے کی ہی ہدایت نہیں دیتی بلکہ ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ ملائکہ کیوں بنائے گئے ہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے.آخر خدا تعالیٰ خود بھی کام کر سکتا تھا.فرشتوں کے بنانے کی ضرورت اسے کیوں پیش آئی.اسی طرح وہ ان کے کام بتاتا ہے.ان کے وجود کے دلائل دیتا ہے، ان کا اور خدا تعالیٰ کا تعلق واضح کرتا ہے، ان کا اور بندوں کا تعلق بیان کرتا ہے.غرض ملائکۃ اللہ کا مسئلہ بھی صرف قرآن کریم نے ہی حل کیا ہے کسی اور کتاب نے اسے چھوا تک نہیں.
Page 64
نبوت (۳) تیسری چیز نبوت ہے.یوں تو نبوت کو ساری قومیں مانتی ہیں.ہندو بھی کہتے ہیں اوتار آئے، عراقی بھی کہتے ہیں نبی آئے.یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ نبی آئے.مگر عجیب بات یہ ہے کہ ادھر تو کہتے ہیں نبی آئے ادھر نبوت کے متعلق وہ کچھ بھی روشنی نہیں ڈالتے.صرف کتاب میں نبی اور اوتار کے الفاظ پائے جانے سے تو کسی کی تسلی نہیں ہوسکتی.جب تک یہ نہ بتایا جائے کہ وہ کیا ہیں، ان کا کیا کام ہوتا ہے، ان کی تعریف کیا ہے،ان کے آنے کی اغراض کیا ہو تی ہیں، ان کی صداقت کی کیا علامات ہو تی ہیں، کس حد تک ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کا کیا مقام ہو تا ہے، اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کیا تعلق ہو تا ہے، ان کے اور بندوں کے درمیان کیا تعلق ہو تا ہے، ان تمام باتوں کا جب تک تفصیلاً پتہ نہ لگے کوئی شخص تسلی کس طرح پا سکتا ہے.قرآن کریم کا ہستی باری تعالیٰ، ملائکہ، نبوت و قضاء و قدر کے متعلق بیان کرنا اور اس کے بیان سے دوسری الہامی کتب پر فضیلت مسئلہ نبوت کے متعلق میں نے ایک دفعہ یہودیوں اور مسیحیوں کو رجسٹری خطوط لکھ کر سوال کئے مگر کسی ایک شخص نے بھی نبوت کی تعریف اپنی کتاب سے ثابت نہ کی بلکہ ایک بشپ نے جو لاہور کا رہنے والا تھا تسلیم کیا کہ ہماری کتب اس بارہ میں بالکل خاموش ہیں.یہ قرآن کریم کی دوسری کتب پر کتنی بڑی فضیلت ہے.قرآن کریم دوسری کتابوں کے مقابلہ میں بہت چھوٹی سی کتاب ہے مگر اس میں تمام ضروری مسائل کا ذکر ہے.اور باتوں کو جانے دو اگر نبی کے نام پر ہی غور کیا جائے تو انبیاء کا کام سمجھ آسکتا ہے.عربی میں رسول اور نبی دو نام ہیں.ان ناموں میں ہی ان کا کام بتا دیا گیا ہے.رسول کے معنے ہوتے ہیں بھیجا ہوا.اور نبی کے معنے ہو تے ہیں بڑی خبر دینے والا.مسلمانوں نے بدقسمتی سے یہ بحث شروع کر دی ہے کہ رسول اور نبی الگ الگ ہو تے ہیں.حالانکہ وہ اگر ان لفظوں پر ہی غور کر لیتے تو اس بحث میں نہ پڑتے.کیا کوئی شخص یہ مان سکتا ہے کہ جو خبر دیتا ہے اسے خدا تعالیٰ نے نہیں بھیجا، اگر اسے خدا تعالیٰ نے نہیں بھیجا تو وہ خبر کیا دے سکتا ہے.اسی طرح اگر کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو کیا وہ منہ بند کر کے بیٹھ جائے گا؟ لازماًوہ کچھ خبریں بھی دےگا.درحقیقت رسول اور نبی یہ دو نام اس کی دو الگ الگ حیثیتوں کی وجہ سے رکھے گئے ہیں.جب اس کا منہ خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تو وہ رسول کہلاتا ہے اور جب اس کا منہ لوگوں کی طرف ہو تا ہے تو وہ نبی کہلاتا ہے.کیا چٹھی رساں ایسا کر سکتے ہیں کہ ڈاک لے کر وہیں بیٹھ جائیں اور کہہ دیں کہ ڈاک ہم نے لینی تھی وہ لے لی ہے کیا افسر انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو.ڈاک تو تمہیں لوگوں کو پہنچا نے کے لئے دی گئی ہے نہ کہ تھیلہ میں بند کر نے کے لئے.اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے کیا وہ وہیں بیٹھ جائے گا یا لوگوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچائے
Page 65
گا اور اگر لوگوں کو وہ خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا تو وہ نبی ہوجائے گا.اور اگر وہ خدا تعالیٰ کا پیغام نہیں سناتا تو پھر نبی کیسا وہ تو جھوٹا ہے.اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور اگر سچا ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کارسول ہے.غرض رسول اور نبی الگ الگ وجود نہیں ہو تے بلکہ دو حیثیتوں کی وجہ سے ان کے یہ دو الگ الگ نام ہو تے ہیں.بہرحال قرآن کریم میں تمام تفصیلات اس طرح بیان کی گئی ہیں کہ انسان کی روح مطمئن ہو جاتی ہے.اس نے نہ صرف نبی کی تعریف بیان کی ہے بلکہ تفصیلی طور پر ان کی آمد کی غرض، ان کے فرائض، ان کی صداقت کی علامات، ان کے اور خدا تعالیٰ کے تعلقات کی تفصیل، ان کے اور بنی نوع انسان کے تعلقات کی تفصیل، ان کی خصوصیات سب بیان کی ہیں اور سیر حاصل طور پر بیان کی ہیں.(۴) قضاء و قدر کے متعلق بھی قرآن کریم کے سوا باقی سب کتابیں خاموش ہیں.اگر کسی غیر مذہب والے سے پوچھا جائے کہ قضاء و قدر کے کیا معنے ہیں تو وہ اس کے متعلق کوئی بھی روشنی اپنی الہامی کتاب سےپیش نہیں کر سکتا.حالانکہ یہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے اور اس کا روحانیت کے ساتھ گہرا تعلق ہے زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ اختیار نہیں جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور یہی قضاء و قدر کے معنے ہیں حالانکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کاموں میں کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ کام ہم سے کون کروا رہا ہے اور جب ہم محسوس ہی نہیں کرتے تو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور اگر اس کا دخل ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے اور پھر یہ کہ کیا سب کاموں میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے یا بعض کاموں میں؟اگر کسی کام میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور کسی کا م میں نہیں تو ہمیں کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ فلاں کام میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور فلاں میں نہیں؟ اگر ہم کہیں گے کہ سب کاموں میں خدا تعالیٰ کا دخل ہے تو چوری ہم کر رہے ہوں گے اور اطمینان سے کہہ دیں گے کہ خدا تعالیٰ ہم سے چوری کروا رہا ہے.فریب ہم کر رہے ہوں گے اور کہہ دیں گے کہ خدا تعالیٰ ہم سے فریب کروا رہا ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کسی کام میں بھی دخل نہیں تو ہماری عبادتیں اور دعائیں لغو ہوجاتی ہیں.اب صرف تیسری صورت ہی رہ جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ بعض کاموں میں دخل دیتا ہے اور بعض کاموں میں نہیں.لیکن اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر مذہب کو بتانا چاہیے کہ وہ کون سے کاموں میں دخل دیتا ہے اور کون سے کاموں میںدخل نہیں دیتا.ورنہ معاملہ مشتبہ ہوجائے گا او ریہ پتہ نہیں لگ سکےگا کہ کس کام میں بندہ آزاد ہے اور کس کام میں وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کے ماتحت ہے.
Page 66
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے پیدا کیا کرتے تھے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے.وہ نہ مانا اور اپنی بات پر اصرار کرتا چلا گیا.آخر تنگ آکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا کہ اچھاحضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر پرندے پید اکیا کرتے تھے تو ان کے پیدا کئے ہوئے پرندے کہاں ہیں اس شخص نے جواب دیا کہ وچے ہی رل مل گئے نے (یعنی خدا تعالیٰ کے پرندوں سے مل جل گئے ہیں)(تحفہ گولڑویہ، روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحہ ۲۰۶) ویسی ہی بات یہاں ہو جاتی ہے.اگر ہمیں پتہ نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا دخل انسانی کاموں میں کس حد تک ہے تو انسانی اعمال کی حقیقت مشتبہ ہو جاتی ہے.اس لئے لازماً مذہب کو بتانا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن میں خدا تعالیٰ دخل دیتا ہے.اور وہ کون سے کام ہیں جن میں خدا تعالیٰ دخل نہیں دیتا.مگر یہ بات صرف قرآن کریم ہی بتاتا ہے باقی سب کتب اس بارہ میں خاموش ہیں کہ قضاء و قدر کے معنے کیا ہیں، قضاء و قدر اور تدبیر کا کیا تعلق ہے، قضاء و قدر کی غرض کیا ہے، قضاء و قدر سے کیوں جبر نہیں نکلتا اور کس طرح اس کےباوجود انسان آزاد ہے اور جہاں آزادنہیں وہاں اسے سزا نہیں ملتی.قضاء و قدر کا دائرہ کیا ہے.ان تمام امور کے بارہ میں صرف قرآن کریم میں روشنی ڈالی گئی ہے باقی سب کتب خاموش ہیں.اگر کسی غیر مذہب والے کا دعویٰ ہو کہ قضاء و قدر کے متعلق صحیح تعلیم اس کی الہامی کتاب میں موجود ہے تو ہم اسے چیلنج کرتے ہیں کہ وہ قرآ ن کریم کے مقابلہ میں اپنی کتاب سے اس مسئلہ کو واضح کرے.مگر ہمیں یقین ہے کہ کوئی دوسرا مذہب اپنی کتاب سے یہ مسئلہ نہیں نکال سکتا.یہ صرف قرآن کریم کی ہی خوبی ہے جو اسے تمام الہامی کتب پر فضیلت دیتی ہے.بَعْث بَعْدَ الْمَوْت (۵) بعث بعد الموت کو لو تو اس بارہ میں بھی باقی کتابیں یا تو خاموش ہیں جیسے بائبل اور وید اور یا پھر ان میں صرف بعض تفصیلات کا ذکر ہے اس کے ثبوت نہیں دیئے، اس کی حکمتیں بیان نہیں کیں، نہ اخروی زندگی کے مقاصد بیان کئے ہیں نہ سزا و جزا کی غرض اور اس کی حکمتیں بیان کی ہیں.ژند اوستا نے ایک حد تک اس مسئلہ کو بیان کیا ہے.لیکن بائبل اور وید دونوں اخروی زندگی کے متعلق بالکل خاموش ہیں.ژند اوستا کو پڑھیں تو اس میں دوزخ اور جنت کا ذکر پڑھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن کریم اور ژند اوستا میں ایک گہرا رشتہ ہے.لیکن دنیوی زندگی کو لیں تو اس کا قرآن کریم کے ساتھ کوئی جوڑ ہی معلوم نہیں ہوتا.دنیوی زندگی کے متعلق بائبل قرآن کریم سے مشابہت رکھتی ہے اور اخروی زندگی کے متعلق ژند اوستا قرآن کریم سے مشابہت رکھتی ہے بہر حال دوسری کتابیں یہ نہیں بتاتیں کہ اخروی زندگی اور دنیوی زندگی میں فرق کیا ہے.جزا و سزا کی کیا غرض اور حکمت ہے یا جزا و سزا
Page 67
کن اصولوں پر مبنی ہے.لیکن قرآن کریم نے بعث بعد الموت کے ثبوت بھی دیئے ہیں.اس کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں.اخروی زندگی کے مقاصد بھی بیان کئے ہیں.جزا و سزا کی اغراض بھی بیان کی ہیں.ان کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں.جنت و دوزخ کی صحیح تفصیلات بھی بیان کی ہیں.غرض آیات الٰہیہ کے بیان کرنے میںمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر ملا ہےوہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے.اسے معیّن طور پر بتایا جا سکتا ہے اور سب مذاہب پر اسلام کی اور سب نبیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کی جا سکتی ہے.میں اوپر بتا چکا ہوں کہ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ میں ان دلائل عقلیہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شناخت اور دین کے امور مہمہ کے سمجھانے کے لئے ضروری ہیں اور ان معجزات و نشانات کی طرف بھی اشارہ ہے جو عقلی دلائل کو مشاہدہ اور یقین کامل کا رنگ بخشتے ہیں.اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم نے دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے امور دینیہ مہمہ کے ثبوت میں ایک سیر کن بحث کی ہے وہاں اس نے ان مسائل کے ثبوت کے لئےوہ معجزات و نشانات بھی پیش کئے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد اور جن پر غور کر نے کے بعد انسان کا علم ذہنی، علم عینی اور یقینی بن جاتا ہے اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست فضیلت انبیاء سابقین پر ثابت کر دی ہے.آنحضرتؐکا سب سے بڑا معجزہ آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے سب سے بڑا معجزہ جو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کا خاتم النبیین ہو نا ہے یعنی تمام کمالاتِ نبوت آپ پر ختم کر دیئے ہیں.یاد رکھنا چاہیے کہ ختم نبوت محض ایک دعویٰ نہیں جیسا کہ مسلمان عوام خیال کرتے ہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ثابتہ ہے جسے نشان کے طور پر ہرہر زمانہ کے لوگ دیکھ اور پرکھ سکتے تھے.ظاہر ہے کہ جو معنے عوام میں خاتم النبیین کے مشہور ہیں وہ تو ایسے معنے ہیں کہ شاید قیامت کے دن کسی پر حجت ہوں تو ہوں اس سے پہلے کسی غیرمسلم سے وہ دعویٰ نہیں منوایا جا سکتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہود و نصاریٰ سے یہ کہا جاتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ان معنوں میں ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا تو اس کی کیا دلیل ان کے سامنے پیش کی جا سکتی تھی اوروہ اسے کب مان سکتے تھے.ظاہر ہے کہ فضیلت تو وہ ہوتی ہے جسے ثابت کیا جا سکے.جسے ثابت نہ کیا جا سکے وہ فضیلت کیا ہوئی.ختم نبوت کا دعویٰ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں سے سب سے بڑا دعویٰ ہے.اگر سب سے بڑا دعویٰ ثابت نہ ہوسکے تو بڑائی کس طرح ثابت ہو گی.صحابہ ؓ کا نصاریٰ یا یہود سے یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے نبیوں پر یہ فضیلت ہے کہ آپ
Page 68
کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، کس قدر مضحکہ خیز ہو جاتا تھا.وہ ہنس کرکہتے کہ(۱) تم تو خود ایک مسیح کی آمد کے معتقد ہو.(۲) کَے آمدی وکَے پیرشُدی ابھی آپ کے رسول کو آئے ہوئے کتنی مدت ہوئی کہ کہتے ہو ان کے بعد نبی نہ آئے گا.گذشتہ انبیاء کے بعد بھی تو فوراً نبی نہ آیا کرتے تھے بالعموم ایک عرصہ کے بعد نبی آتے تھے تمہارے نبی مسیح علیہ السلام کے چھ سو سال بعد آئے ہیں چھ سو سال تو انتظار کرو.اس کا جواب مسلمان کیا دےسکتے تھے.گویا ختم نبوت کے اس مفہوم کے منوانے کے لئے چھ سو سال کا انتظار ضروری تھا چھ سو سال تک آپ کا ختم نبوت کا دعویٰ بے دلیل رہتا تھا.مگر چھ سو سال کے بعد بھی تو مسلما ن کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ یہ دلیل نصاریٰ و یہود کی پھر بھی موجود تھی کہ تم اس آنے والے نبی کے حق میں کیا کہتے ہو جسے تم مسیح کا نام دیتے ہو اور پھر وہ اس وقت کہہ سکتے تھے کہ موسٰی کے مرنے کے چند سال بعد یوشعؑ نبی ظاہر ہوا.لیکن یوسف نبی کے اڑھائی تین سو سال بعد موسٰی نبی ظاہر ہوئے.حتی کہ بنی اسرائیل نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یوسفؑ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو گا.پس معلوم ہوا کہ کبھی ایک نبی کے بعد جلد دوسرا نبی آجاتا ہے اور کبھی لمبے وقفہ کے بعد.خود تمہارے نبی تمہارے اپنے دعویٰ کے مطابق حضرت مسیح کے چھ سو سال بعد آئے پس صدیوں کا خالی گذر جانا تو کوئی ثبوت نہیں کہ فلاں مدعی کےبعد کوئی نبی نہ آئے گا.غرض گو یہ درست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی نہ آئے گا.مگر دشمن پر ہم ان معنوں میں نبی کریمؐ کی فضیلت کو ثابت نہیںکر سکتے اور قیامت تک ختم نبوت کا یہ مفہوم ایک دشمن اسلام پر بطور حجت کے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ آپ آخری نبی ہیں.پس ختم نبوت کے اگر یہ معنے لئے جائیں تو ختم نبوت کی فضیلت جو آنحضرتؐکی سب سےبڑی فضیلت ہے پردۂ اخفا میں ہی قیامت تک چلی جائے گی اور قیامت کو اس کا ثابت ہو نا کسی کے لئے بھی فائدہ بخش نہ ہو گا.ہاں اگر ختم نبوت کے یہ معنے کئے جائیں کہ پہلے نبی ایک ایک قوم کے نبیوں کی تعلیم کو ختم کرتےتھے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دنیا کے اور سب قوموں کے نبیوں کی نبوت کو ختم کیا ہے تو یہ دعویٰ آپ کا پہلے دن سے ہی ثابت کیا جا سکتا تھا اور اب تک اور قیامت تک ثابت کیا جاسکتا ہے.اس دعویٰ میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ سچے نبی کی علامت سابق کتب اور قرآن کریم اور عقل سے یہ معلوم ہو تی ہے کہ اس کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو اور اس کے تعلق کی نسبت سے اس کے پیرؤوں کا بھی خدا تعالیٰ سے تعلق ہو، تامنکروں پر حجت قطعیہ سے ثابت کیا جا سکے کہ اس کا منجانب اللہ ہو نے کا دعویٰ سچا اور حق پر مبنی ہے.اب اس دلیل کو اگر صحیح سمجھا جائے اور اس کے صحیح ہو نے میں کوئی شبہ نہیں سمجھا جاسکتا تو ایک مسلمان سب مذاہب کے لوگوں کو پہلے دن سے چیلنج دے سکتا تھا کہ ہمارے نبی کے خاتم النبیین ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ اس
Page 69
نے سب نبیوں کی نبوت کو ختم کر دیا ہے اب کسی نبی کی امت میں کوئی شخص خدا رسیدہ نہیں ہوسکتاصرف آپ ہی کے اتباع کا براہ راست تعلق خدا تعالیٰ سے ہے.سیدھی بات ہے کہ یا تو اسلام کے منکر اس کا یہ جواب دیتے کہ خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہوہی نہیں سکتا اور یا یہ جواب دیتے کہ ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا خدا تعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے.دونوں صورتوں میں فیصلہ آسان ہو جاتا ہے.پہلے جواب کی صورت میں مسلمان آسانی سے اپنے برگزیدہ وجودوں کے نشانات پیش کر کے ثابت کر سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ کا ہم سے براہ راست تعلق ہے اور چونکہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس راستہ کو بند قرار دے چکے ہو تے لازماً اس ثبوت کے ساتھ یہ بھی ثابت ہوجاتا کہ خدا تعالیٰ کا براہ راست تعلق انبیاء کی جماعتو ں سے ضرور ہو تا ہے مگر اس وقت وہ تعلق صرف امت محمدیہ سے ہے اور کسی امت کے افراد سے نہیں.پس معلوم ہوا کہ ان نبیوں کی نبوت ختم ہو چکی اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے اور آپ کا ختم نبوت کا دعویٰ ثابت ہو جاتا اور دوسرے جواب کی صورت میں مسلمان ان لوگوں سے مطالبہ کرتے کہ اپنے موجودہ بزرگوں کے الہامات اور وحی کو پیش کرو تاکہ ان کے صدق و کذب کو پرکھا جا سکے اور چونکہ فی الواقعہ دعویٰ محمدیت کے بعد باقی تمام اقوام سے براہ راست تعلق (سوائے ایک عارضی تعلق کے ) خدا تعالیٰ کا قطع ہو چکا ہے اس لئے لازماً وہ لوگ اس مطالبہ کو پورا نہ کر سکتے تھے اور اس طرح بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ختم نبوت کا دعویٰ ثابت ہو جاتا تھا اور یہ معنے جو میں نے کئے ہیں صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک نشان اور آیت ہے.کیونکہ محض دعویٰ وہ ہو تا ہے جسے انسان اپنی طرف سے پیش کرتا ہے اور خارج میں اس کا ثبوت نہیں ملتا.لیکن نشان اور آیت کا ثبوت خارج میںموجود ہوتا ہے اور ختم نبوت کے وہ معنے جو میں نے اوپر کئے ہیں وہ ایسے معنے ہیں کہ ان کا وجود خارج میں موجود تھا اور مسلمانوں اور غیر اقوام میں دونوں میں موجود تھا مسلمانوں میں مثبت حیثیت سے اور غیر مسلموں میں منفی کی حیثیت میں.ختم نبوت کے دوسرے معنے کمال نبوت کے ہیں اور یہی معنے متبادر ہیں کیونکہ ختم نبوت کی آیت میں خاتم تا کی زبر سے آیا ہے او رخاتم تا کی زبر سے آئے تو اس کے معنے مہر کے ہو تے ہیںاور مہر تصدیق کے لئے لگائی جاتی ہے پس خاتم النبیین کے معنے ہوئے کہ یہ نبی نبیوں کی مہر ہے اس کی تصدیق کے بغیر کوئی نبی نہیں ہو سکتا.یہ معنے بھی ہروقت ثابت تھے.سابق نبیوں کے بارہ میں اس طرح کہ کسی نبی کی نبوت قرآن کریم کی شہادت کے بغیر ثابت نہیںہو سکتی.مسیحؑ کو انجیل سے، موسٰی کو تورات سے، کرشنؑ اور رامچندرؑ کو ان کی کتب سے، زردشتؑ کو اوستا سے سچا نبی ثابت نہیں کیا جا سکتا.قرآنی دلائل اور نشانات سے ہی ان لوگوں کی سچائی ثابت کی جا سکے گی اور آئندہ کوئی نبی آئے تو
Page 70
اس کے لئے آپؐمہر تھے یعنی آپ سے باہر جا کر اور آپ سے الگ ہو کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا.اگر کوئی کہے کہ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن زندہ دلیل موجود ہے.دوسرا آزاد نبی تبھی آیا کرتا ہے جبکہ پہلے نبی کی کتاب میں خرابی پیدا ہو گئی ہو مگر قرآن کریم پہلے دن کی طرح اپنے الفاظ میں اور تاثیر میںمحفوظ ہے.اس کے الفاظ کی حفاظت کے دشمن بھی اقراری ہیں.اس کی تاثیر کے شاہد وہ روحانی بزرگ ہیں جو ہر وقت اسلام میں موجود رہتے ہیں.وہ کبھی مجدد کہلاتے ہیں کبھی امتی نبی کبھی ولی اللہ مگر رہتے ہمیشہ ہیں اور سب کے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی غلامی کا اقرار کرتے ہیں.پس اس سے زیادہ ثبوت اور ختم نبوت کا کیا ممکن ہے.خلاصہ یہ کہ ختم نبوت سب سے بڑا نشان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ہے جو میرے بیان کردہ معنوں کے رو سے ہمیشہ ہی ثابت ہے او رہر وقت دشمنوںپر اس کی صداقت ثابت کی جاسکتی ہے اور ہماری طرف سے کی جارہی ہے.آنحضرت صلعم پر خدا تعالیٰ کی کامل تجلی دوسری آیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ نے ظاہر کی وہ یہ ہے کہ آپ کو دَنَا فَتَدَلّٰى کا بلند مقام ملا.گویامحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل تجلی ظاہر کی.پھر آپؐکے متعلق ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ( اٰل عـمران: ۳۲) اے محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) تو ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجزن ہے اور تم چاہتے ہو کہ وہ تم سے پیار کرے تو تم میری اطاعت کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کر نے لگ جائے گا.پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر آپ کی شان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے.وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ۠ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ١ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓىِٕكَ رَفِيْقًا(النسآء: ۷۰) یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات نازل کئے یعنی نبیوں میں یا صدیقوں میں، شہیدوں میں یا صلحا ء میں اور یہ لوگ بہترین رفیق ہیں.دیکھو یہ کتنا بڑا انعام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ آپ کی متابعت اور پیروی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور صدیقیت اور شہادت اور صالحیت کا مقام رکھ دیا.اور در حقیقت بڑا آدمی وہی ہو تا ہے جس کے ماتحت بڑے بڑے آدمی ہوں.ایک پرائمری کے مدرس اور ایم اے کے پروفیسر میں کیا فرق ہوتا ہے یہی کہ پرائمری کے مدرس سے پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں اور ایم اے کے پروفیسر سے پڑھنے والے بڑے بڑے طالب علم ہوتے ہیں.لفظ استاد میں تو دونوں شریک ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک کو بڑا کہا
Page 71
جاتا ہے اس لئے کہ وہ بڑے لوگوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے شاگرد بڑے درجہ کے ہو تے ہیں اور دوسرے کو چھوٹا کہا جاتا ہے اس لئے کہ وہ چھوٹوں کو پڑھاتا ہے اور اس کے شاگرد چھوٹے درجہ کے ہو تے ہیں.اسی طرح نبی تو سارے ہیں مگر بڑا نبی وہی ہو گا جس کے مخاطب بڑی قابلیت کے ہوں.اس حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ ایسے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات نازل کئے یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے گروہ میں اور یہ بہترین رفیق ہیں گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے متعلق فرمایا کہ وہ نبیوں میں شامل ہوں گے، وہ صدیقوں میں شامل ہوں گے، وہ شہیدوں میں شامل ہوں گے، وہ صلحاء میں شامل ہو ں گے لیکن جہاں باقی نبیوںکا ذکر فرمایا ہے وہاں نبیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ فرما تا ہے.وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖۤ اُولٰٓىِٕكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ۠١ۖۗ وَ الشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ (الحدید:۲۰) یہاںرسول نہیں کہا بلکہ رُسل کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں انبیاء سابقین کی طرف اشارہ ہے اور فرماتا ہے کہ دوسرے رسولوں کے کامل متبع صرف صدیق اور شہید بن سکتے تھے نبی نہیں بن سکتے تھے.گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نمایاں سلوک ہے کہ آپ کے کامل متبع نعمت نبوت بھی حاصل کر سکتے ہیں جبکہ پہلے نبیوں کی اتباع میں صرف صدیقیت اور شہادت کا درجہ مل سکتا تھا.اس بات کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لَوْکَانَ مُوْسیٰ وَعِیْسٰی حَیَّیْنِ لَمَاوَسِعَھُمَا اِلَّااتِّبَاعِیْ(الیواقیت الـجواہر الـجزء الثانی صفحہ ۳۴۲) یعنی اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام زندہ ہوتے تو میری اطاعت اور فرمانبرداری کے سوا ان کے لئے اور کوئی چارہ نہیں تھا.غرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے نبیوں پر یہ مقامِ فضیلت عطا فرمایا ہے کہ آپ کے کامل شاگرد نبوت کے مقام پر پہنچ سکتے ہیں.مگر ایسی نبوت جو ظلّی اور بروزی ہو.یعنی نبی ہو نے کے باوجود وہ آپؐکے کامل غلام اور شاگرد ہوں گے.بعض لوگ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرتے ہیں کیونکہ نبی کے نام میں ہم اَوروں کو بھی آپ کا شریک ٹھہراتے ہیں.مگریہ اعتراض قلت تدبر کا نتیجہ ہے دنیا میں ہزاروں جگہ یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ استاد بھی ایم اے ہو تا ہے اور اس کا شاگرد بھی ایم اے ہو تا ہے مگر کیا وہ دونوں ایک ہو تے ہیں؟ کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کے کالج کا پرنسپل بھی ایم اے ہوتا ہے دوسرے پروفیسر بھی ایم اے ہو تے ہیں اور آگے ان کے شاگرد بھی ایم اے پاس کر لیتے ہیں اس میں ان کی کیا ہتک ہو جاتی ہے.جس پروفیسر کے زیادہ شاگرد پاس ہوکر ایم اے
Page 72
بن جائیں اس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے حالانکہ وہ سب کے سب بظاہر اس کے نام میں شریک ہوجاتے ہیں.پس نام کی شرکت کوئی معنے نہیں رکھتی اصل چیز درجہ کی شرکت ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہےکہ کوئی شخص اپنے درجہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے نہیں بڑھ سکتا وہ بہر حال آپ کا غلام ہی رہے گا.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شاگرد نے اگر آپ کی غلامی میں نبوت کو پالیا تو وہ آپ کی عزت کو بڑھانے کا موجب ہے، گھٹانے کا موجب نہیں.جیسے ایک پرنسپل کے شاگردوں کا ایم اے ہو جانا کوئی ہتک نہیں ہوتی بلکہ اس کی عزت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ جن کو پڑھائیں وہ بھی ایم اے ہوں.غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تو نبی بن سکتے ہیں مگر باقی نبیوں کے شاگرد صرف صدیق اور شہید کے درجہ تک پہنچ سکتے تھے اور یہ آپ کو انبیائے سابقین پر ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہے.دو قسم کے انبیاء (۲)اب ہم دعائے ابراہیمی کے یُعَلِّمُھُمُ الْکِتٰبَ والےحصہ کو لیتے ہیں.سویاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء دو قسم کے ہو تے ہیں.ایک صاحب شریعت اور ایک بے شریعت.دونوں کاکام تعلیم کتا ب ہو تا ہے.صاحبِ شریعت نبی کاکام بھی تعلیمِ کتاب ہوتا ہے اور بے شریعت نبی کاکام بھی تعلیمِ کتاب ہو تا ہے.ہاں صاحبِ شریعت نبی کتاب بھی لاتے ہیں اور غیر صاحب شریعت نبی کتاب نہیں لاتے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صاحبِ شریعت نبی تھے اس لئے آپ کا مقابلہ سب نبیوں سے تھا خواہ وہ شریعت لائے یا نہ لائےلیکن اس جگہ ہم آپ کا مقابلہ صاحبِ شریعت نبیوں سے کرتے ہیں.جب صاحبِ شریعت انبیاءپر آپ کی فضیلت ثابت ہوجائے گی تو یہ لازمی بات ہے کہ غیر شرعی نبیوں سے آپ خودبخود افضل ثابت ہو جائیں گے کیونکہ ایسے نبی بہر حال اپنے سابق شریعت والے نبی سے درجہ میں ادنیٰ ہو تے ہیں.آنحضرت کی جملہ شریعت لانے والے انبیاء پر فضیلت قرآن کریم کی رو سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلےجو صاحبِ شریعت انبیاء آئے وہ دو نبی ہیں (۱) حضرت نوح علیہ السلام اور (۲)حضرت موسیٰ علیہ السلام.حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تو موجود ہے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کتاب موجود نہیں.قرآن کریم میں صرف اتنا ذکر آتا ہے.وَ اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ (الصّٰفّٰت:۸۴) یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے.شریعت نوح علیہ السلام کی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے تابع نبی تھے.حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت سلیمان اور یحییٰ علیہم السلام موسوی شریعت کے تابع تھےمگر ان دو صاحب شریعت نبیوں کے علاوہ قرآن کریم نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ
Page 73
اِنْ مِّنْ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیْھَا نَذِیْرٌ (فاطر:۲۵) دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں جس میں ہمارا کوئی نہ کوئی نبی نہ آیا ہو.اگر کوئی شخص آکر ہمیں کہے کہ فلاں نبی بھی دنیا میں گذرا ہے اور اس کے حالات بظاہر نبیوں سے ملتے ہوں سوائے ان قصوں کے جو عام طور پر ساتھ ملا لئے جاتے ہیں تو اگر ہم کہہ دیں کہ وہ نبی نہیں تو ہم اپنے دین کا آپ انکار کرتے ہیں.مثلاً ایک ہندو آکر کہتا ہے کہ وید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے ہیں اور ہم کہہ دیں کے تم جھوٹ بولتے ہو.وہ کہے رام چندر جی نبی تھے اور ہم کہیں جھوٹے تھے.وہ کہے کرشن جی نبی تھے اور ان کی کتاب گیتا بھی موجود ہے جس میں ان کے بعض الہامات درج ہیں اور ہم کہیں یہ بالکل جھوٹ ہے.پھر بدھ ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ بدھ نام کے ایک نبی ہندوستان میں آئے ہیں جن سے خدا تعالیٰ باتیں کرتا تھا اور ہم کہہ دیں کہ وہ نعوذ باللہ فریبی تھے تووہ فوراً قرآن کریم سے یہ آیت نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ ہرقوم میں نبی آئے.اب بتاؤ اگر کرشن جی نبی نہیں، اگر رام چندر جی نبی نہیں، اگر بدھ نبی نہیں تو ہندوستان میں پھر کون سا نبی آیا ہے.ہم نے ان تینوں کو تو جھوٹا کہہ دیا اور نبی ہم کہاں سے لائیں گے.سوائے اس کے کہ ہم کہہ دیں ہمیں معلوم نہیں.وہ کہیں گے تمہارے قرآن نے تو کہا ہے کہ ہر ملک اور ہرقوم میں نبی آئے ہیں تم اس کا ثبوت دو.اس صورت میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا تو ڈھیٹ آدمی کی طرح نہیںنہیں کرتے رہیں اور یا ہم بھی اس پٹھان کا طریقِ عمل اختیار کریں جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے ایک روپیہ کے خربوزے خریدے.وہ خربوزے میٹھے نہیں تھے اس نے غصہ میں آ کر سب پر پیشاب کر دیا اور پھر مزدوری کرنے چلا گیا.جب پیٹ خالی ہوا اور بھوک نے ستایا تو وہ خربوزوں کے پاس واپس آیا.ایک خربوزہ اٹھایا اور یہ کہہ کر کہ اس پر تو میں نے پیشاب نہیں کیا تھا اس نے کھا لیا اسی طرح باری باری وہ تمام خربوزے کھاتا گیا.جب صرف ایک خربوزہ رہ گیا اور اسے بھوک نے پھر ستایا تو وہ کہنے لگا خوہ جن خربوزوں پر میں نے پیشاب کیا تھا وہ تو میں کھا گیا اس پر تو پیشاب ہی نہیں کیا تھا یہ کہہ کر وہ خربوزہ بھی کھا گیا.یہی حال ہمارا ہو گا پہلے تو ہم سب کو جھوٹا کہہ دیں گے اور جب وہ کہے گا بولو ہندوستان میں پھر کون سا نبی آیا ہے؟ تو اس کے سوا ہم کہہ بھی کیا سکتے ہیں کہ اچھا رام چندر جی کو ہی نبی مان لیتے ہیں، کرشن جی کو ہی نبی مان لیتے ہیں، بدھ کو ہی نبی مان لیتے ہیں اور جب مجبور ہوکر ہم نے یہ کہنا ہے تو کیوں نہ سیدھی طرح ہم انہیں پہلے ہی نبی مان لیں.کرشن جی اور رام چندر جی کے متعلق ہمارے صوفیا ء اور اولیاء نے بھی خوابیں دیکھی ہیں.حضرت مظہر جانِ جاناں کے پاس ایک شخص آیااور اس نے کہا رام چند رجی اور کرشن جی جھوٹے ہیں.چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ
Page 74
آگ جل رہی ہے حضرت کرشن آگ کے وسط میں کھڑے ہیں اور رام چند رجی کنارے پر کھڑے ہیں.معلوم ہوا کہ یہ دونوں جھوٹے ہیں.آپ نے فرمایا خواب کی تعبیر خواب کی زبان میں ہی ہو تی ہے.آگ کے معنے ہیں محبت الٰہی.حضرت کرشن جی کے آگ میں کھڑا ہو نے کا مطلب یہ ہےکہ آپ محبتِ الٰہی کے مرکز میں کھڑے ہیں اور رام چندر جی چونکہ آپ سے چھوٹے درجہ کے ہیں اس لئے وہ کنارے پر کھڑے ہیں.غرض قرآن کریم کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہر قوم میں نبی گذرے ہیں.اب اگر کوئی آ کر کہے کہ ہماری قوم میں فلاںنبی گذرا ہے اور اس کے واقعات نبیوں کے سے ہوں تو ہم کہیں گے سبحان اللہ کتنی بڑی آسانی پید اہو گئی.میں تو عیسائیوں اور یہودیوں اور ہندوؤں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے آپ کاکام بہت مشکل ہے.مثلاً جب یہودی کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ہندو کہیں گے رام رام وہ نبی کیسے ہوئے.اگرہم کہیں گے کہ ایران میں زردشت علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہودیوں اور ہندوؤں دونوں کو بپتا پڑ جائے گی.ہندو رام رام کہنے لگ جائیں گے اور یہودی ایلوہیم ایلوہیم.اے اللہ میں کیا کروں.اچھا کوئی تدبیر سوچو جس سے زردشت علیہ السلام نبی ثابت نہ ہوں اگرہم زردشتیوں سے کہیں گےکہ ہندوستان میں بدھ نبی آیا ہے تو وہ کہیں گے ہم مارے گئے.اچھا کوئی تدبیر سوچو جس سے اس کی نبوت ثابت نہ ہو لیکن قرآن کریم نے اِنْ مِّنْ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیْھَا نَذِیْرٌ (فاطر:۲۵) کہہ کر بڑی آسانی پیدا کر دی ہے.اگر کوئی ہندو آکر کہے کہ ہندوستان میں رام چندر جی نبی گذرے ہیں،کرشن جی نبی گذرے ہیں تو میں کہوں گا سبحان اللہ کتنی بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے مجھےمحنت نہیں کرنی پڑی.تم نے خود بتا دیا.میرے قرآن نے بھی تو یہی کہا ہے.اگر تم کہتے کہ بتاؤ ہندوستان میں کون سا نبی گذرا ہےتو مجھے مصیبت پڑ جاتی.میں چین میں جاتا ہوں اور سنتا ہوں کہ یہاں کنفیوشس علیہ السلام خدا تعالیٰ کے ایک نبی گذرے ہیں تو عیسائی اور یہودی شور مچا دیتے ہیںکہ یہ کہاں کے نبی ہو گئے.لیکن میں کہتا ہوں سبحان اللہ کیا ہی آسانی پید اہو گئی ہے اگر وہ مجھ سے پو چھتے کہ اچھا بتاؤ ہم میں کون سا نبی آیا تھا تو میں مشکل میں پڑ جاتا.انہوں نے خود بتا دیا اور میں محنت سے بچ گیا.قرآن کریم بھی تو یہی کہتا ہے اِنْ مِّنْ اُمَّۃٍ اِلَّا خَلَا فِیْھَا نَذِیْرٌ.میں ایران جاتاہوں تووہاں کے لوگ کہتے ہیں یہاں زردشت علیہ السلام نبی ہوئے ہیں.یہ سن کر یہودی اور عیسائی اور ہندو تو سر پیٹ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاں ہی نبی گذرے ہیں لیکن یہ سن کر میرا چہرہ بشاش ہو جاتا ہے.میں کہتا ہوں سبحان اللہ آپ نے خود ہی بتا دیا ورنہ مجھے بہت محنت کر نی پڑتی.میرے قرآن میں بھی یہی لکھا ہے.غرض جن قوموں میں کوئی نبی گذرا ہے اور اس نے اپنے وقت میں ان کی اصلاح کی ہے اور اس پر عذاب بھی
Page 75
نازل نہیں ہوا.کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹے نبیوں پر عذاب آتا ہے.ہم الحمد اللہ کہہ کر اسے قبول کر لیں گے.پس اصولاً ہر قوم میں نبی آئے ہیں لیکن ان میں سے حضرت زردشت ؑ اور حضرت موسٰی دو معلوم نبی ہیں جن کی شریعت موجود ہے.ویدوں کے رشیوں کا کچھ پتا نہیں.ویدوں نے شریعت ضرور پیش کی ہے مگر نبی کے نام کا سوال رہ جاتا ہے اور یہ پتہ نہیں لگتا کہ وید کس پر نازل ہوئے.اس لئے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے مقابلہ نہیں کرسکتے.اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت موجود نہیں البتہ ایک اور شخص ہے جس کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ اس نے کچھ قوانین پیش کئے لیکن شریعت کا پوراپتہ نہیںلگتا.الہام کا ذکر اس کی تحریروں میں ضرور ہے او ریہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ توحید کا قائل تھا اور اس نے اخلاق کے بہت عمدہ اصول پیش کئے ہیں وہ حمو رابی تھا.جس کے بعض احکام عمدہ تعلیم پر مشتمل ہیں.لیکن پوری تفصیل معلوم نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے کوئی نئی شریعت پیش کی تھی یا اپنے سے پہلے کسی نبی کی شریعت پیش کی تھی.پس حقیقتاً صرف دو ہی نبی رہ جاتے ہیں جن کی شریعت معلوم ہے (۱) حضرت زردشت علیہ السلام (۲)حضرت موسیٰ علیہ السلام.یہ ظاہر ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتاجو تعلیم کو چھپائے.یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کو پیغام دے کر لوگوں کی طرف بھیجے اور وہ اس کو چھپائے.پس وہ شریعت کو تو نہیں چھپا سکتا.ہاں دوسرے الہاموں کو مصلحتِ وقتی کے ماتحت چھپایا جا سکتا ہے.جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے تو آپ کو رستہ میں بتایا گیا کہ آپ کا مقابلہ مکہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ ہو گا.مگر ساتھ ہی یہ سمجھادیا گیا کہ یہ الہام ابھی ظاہر نہ کیا جائے.بعد میں جب آپ نے مناسب سمجھا تو صحابہ ؓ کو وہ الہام بتایا.یہ امتحان کی ایک صورت تھی.لیکن شریعت والی تعلیم نہیں چھپا ئی جا سکتی.پس تعلیمِ کتاب کا کام درحقیقت تمام انبیاء کرتے ہیں.اس لئے یہاں سوال پید اہو تا ہے کہ جب سب نبی ہی کتاب سکھا نے آئے تھے اور ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں تو پھر آپؐکی ان پر فضیلت کیسے ثابت ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مقابلہ اظہارِ تعلیم میں نہیں بلکہ کمالِ تعلیم میں ہے.اظہارِ تعلیم میں تو سب برابر ہیں لیکن کمالِ تعلیم کے لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملا اس میں کوئی دوسرا نبی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا.چنانچہ اَلْکِتَابِ کے لفظ میں الف لام کمال کے معنے دیتے ہیں جو لغت عرب سے ثابت ہیں اور اسی کی طرف یُعَلِّمُکُمُ الْکِتٰبَ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ نبی تم کو کامل کتاب سکھاتا ہے(مغنی اللبیب).جیسا کہ میں اوپر بتا آیا ہوں شریعت والے معلوم نبی صرف دو ہیں.حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زردشت علیہ السلام.ان میں سے ایک نبی کی کتاب تورات ہے اور دوسرے نبی کی کتاب اوستا.جب ہم قرآن کریم کا
Page 76
مقابلہ ان دونوں کتابوں سے کرتے ہیں تو ہمیں یہ عظیم الشان فرق نظر آتا ہے کہ (اوّل) تعلیم کی جو اصل غرض ہے وہ قرآن کریم کے سوا باقی تمام کتابوں میں مفقود ہے.یہ ظاہر ہے کہ شریعت خدا تعالیٰ نے کسی اپنے لطف کے لئے نازل نہیں کی.جیسے سپین میں لوگوں کو بیل لڑوانے کا شوق ہے یا ہندوستا ن میں لوگ ہاتھی لڑوایا کرتے تھے اور بادشاہ پاس بیٹھ کر تماشا دیکھا کرتے تھے.یہ تو خدا تعالیٰ کی غرض نہیںہو سکتی تھی کہ ہم سخت سردی کے موسم میں وضوکے لئے ہاتھ دھو رہے ہوں اور خدا تعالیٰ آسمان پر ہنس رہا ہو.ہم روزے رکھ رہے ہوں اور وہ یہ دیکھ کر کہ ہمارے قدم نہیں اٹھ رہے اور بھوک کی وجہ سے ہماری آنکھیں زرد ہو رہی ہیں آسمان پر قہقے مار رہا ہو.یہ تو اس سے امید نہیں کی جاسکتی.بہر حال اس نے شریعت ہمارے فائدے کے لئے نازل کی ہے.دنیا میں حکومتیں بھی خواہ وہ کتنی ہی معمولی ہوں جب کوئی قانون بناتی ہیں توان میں سے کوئی شاذ و نادر ہی لغو ہوتا ہے.بالعموم ان میں کوئی نہ کوئی رعایا کا فائدہ مدّ ِنظر ہو تا ہے.اسی طرح خدا تعالیٰ کے احکام میں بھی انسان کے لئے کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور مدّ ِنظر ہو تی ہے.لیکن سوائےقرآن کریم کے جتنی بھی الہامی کتب ہیں ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شریعت کوایک چٹی کے طور پر پیش کیا ہے.وید تو بالکل پردوں تلے ہیں.ان سے شریعت کا کوئی پتہ نہیں لگتا.تورات اور ژند اوستا کو پڑھنے سے بھی یہ تو پتہ چلتاہے کہ ان میں شریعت موجود ہے لیکن ایسا معلوم ہو تا ہے جیسے شریعت اس لئے نہیں کہ اس میں انسان کا نفع ہے بلکہ اس لئے ہے کہ خدا یوں چاہتا ہے جس کی وجہ سے شریعت کی اصل غرض جو اصلاح ہے فوت ہو جاتی ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان میں بعض احکام ایسے بھی ہیں جو انسان کے نفع کے لئے ہیں.لیکن اتفاقی طور پر کسی ایسے حکم کا نکل آنا اور بات ہے.یہ صرف قرآن کریم نے ہی بتایا ہے کہ سب احکام انسان کے فائدہ کے لئے ہیں.بے شک وہ بعض دفعہ بندے کا امتحان بھی لیتا ہے مگر اصل حکم انسان کے فائدہ کے لئے ہی ہو تا ہے.وہ فرماتا ہے لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ( الحج:۳۸) قربانیوں کو ذبح کرنے کا حکم دینے سے ہمارا یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی بوٹیاں پہنچتی ہیں، خدا تعالیٰ کو ان کا خون اور بوٹیاں نہیں پہنچتیں بلکہ وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس کے ماتحت تم قربانی کرتے ہو.ورنہ گوشت تو ہم تمہیں ہی کھلا دیتےہیں.ہم اگر تم سے قربانیاں کرواتے ہیں تو اس لئے تا تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو، تمہارے اندر خشیت پیدا ہو، تمہارے اندر نیکی اور صلاحیت پید اہو.یہ احکام محض چٹی کے طور پر نہیں.(۲)شریعت کا دائرہ کیا ہے.وہ کن امور میں حکم دیتی ہے اور کن میں نہیں اس بارہ میں بھی سب کتب خاموش ہیں.صرف قرآن کریم ہی روشنی ڈالتا ہے آخر یہ واضح بات ہے کہ شریعت بعض کاموں میں دخل دیتی ہے اور بعض
Page 77
میں دخل نہیں دیتی.اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں دخل نہیں دیتی.بھول کر چھوڑ دیتی ہے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہے؟ ان چیزوں کا صرف قرآن کریم نے ہی ذکر کیا ہے باقی سب کتابیں خاموش ہیں اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو قرآن کریم کو دوسری کتب پر حاصل ہے.(۳) شریعت کے ہو تے ہوئے انسانی عقل کی ضرورت یا عقل کے ہوتے ہوئے شریعت کی ضرورت.یہ بھی ایک اہم سوال ہے جس کے حل کئے بغیر شریعت کی ضرورت تسلیم نہیں کی جا سکتی.جاہل تو ہر بات مولوی سے پوچھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عقل کی کوئی ضرورت نہیں.یہ رواج خصوصاً یو پی میں پایا جاتا ہے.اس پر بعض مولوی اپنے پاس سے ہی مسئلہ بنا کر بتا دیتے ہیں.میرے ایک عزیز ڈاکٹر ہیں وہ ایک دن شکار کے لئے باہر گئے اور انہوں نے ایک ہرن مارا.ایک زمیندار بھاگا بھاگا ان کے پاس آیا اور کہا بابو جی ! کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تکبیر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہی تکبیر ہے جسے پڑھ کر ہم بکرے اور مرغے ذبح کرتے ہیں.اس نے کہا نہیں سب کی تکبیر ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے.ہم کو جو ملّاں نے ہرن کی تکبیر بتائی ہے وہ یہ ہے کاہے کو اُچھلت، کاہے کو کودت، کا ہے کو کھاوت پرایو کھیت، تجھ کو آئی جِلّت ہم کو آئی اِجّت اللہ اکبر.غرض عوام الناس تو سمجھتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے اور وہ اپنے مولوی سے پو چھتے ہیں کہ مولوی صاحب چھپائیے نہ ہمیں بتا دیجئےکہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے.وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ ہم سے اصل مسئلہ چھپاتے ہیں بتاتے نہیں.اب جو عالم ہو گا وہ تو ان کو کہہ دے گا کہ جاؤ میاں اس کا بھی وہی حکم ہے جو فلاں کام کا ہے اور جو جاہل مولوی ہو گا وہ اپنے پاس سے کوئی ڈھکوسلہ بتا دے گا تاکہ اس کی عزت بنی رہے.ہندوستان کے بعض علاقوں میں رواج ہے کہ ہر گھر میں ایک چھری رکھی ہوئی ہوتی ہے جس سے وہ جانور ذبح کرتے ہیں.نہ بسم اللہ اور نہ اللہ اکبر کچھ نہیں پڑھتے.وہ کہتے ہیں کہ اس چھری پر ملّاں تکبیر پڑھ گیا تھا اس لئے اب نئی تکبیر کی ضرورت نہیں.یہودیوں میں بھی یہی رواج تھا اور ہے.انہوں نے چھریاں رکھی ہوئی ہیں.علما ء ایک دفعہ ان پر تکبیر پڑھ جاتے اور پھر انہی سے وہ جانور ذبح کر لیا کرتے ہیں.تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی.اس کے مقابلہ میں تعلیم یافتہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے کاموں سے خدا تعالیٰ کا کیا تعلق.کیا ہم احمق ہیں.کسی زمانہ میں جاہلوں کے لئے خدا تعالیٰ نےاحکام نازل کئے تھے.ہم تو ہرقسم کے اصولوں کو جانتے ہیں.علوم و فنون سے آگاہ ہیں.عقل ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ ان احکام کا کوئی تعلق نہیں.غرض عوام الناس تو شریعت کو ان حدود میں لے جانا چاہتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ اسے نہیں لے جانا چا ہتا اور تعلیم یافتہ طبقہ عقل کو ان حدود میں رکھنا چا ہتا ہے جن میں خدا تعالیٰ اسے نہیں رکھنا چا ہتا.اب یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے
Page 78
کہ وہ بتائے کہ شریعت کے ہو تے ہوئےانسانی عقل کی کیوں ضرورت ہے.یا عقل کے ہو تے ہوئے شریعت کی کیوں ضرورت ہے.مگر سوائے قرآن کریم کے اور کوئی کتاب اس پر روشنی نہیںڈالتی.اب ہم تفصیلات کو لیتے ہیں.پہلے اصولِ شرائع ہیں.اسلام نے اصول شرائع پانچ قرار دیئے ہیں.(۱) ایمان باللہ.جس میں صفات، ملائکہ، انبیاء، قضاء و قدر، بعث بعد الموت سب چیزیں شامل ہیں.اس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے.(۲) عبادت.یہ تین قسم کی ہو تی ہے (۱) عبادت مشتمل بر حرکات جسم وذکر الٰہی جیسے نماز (۲) عبادت ذکری جیسے ذکر الٰہی (۳) عبادت فکری یعنی تدبّر در صفات الٰہیہ.قرآن کریم نے ان سب قسموں کی عبادت کا ذکر کیا ہے.نماز اسلامی کچھ حرکات جسم اور کچھ اذکار پر مشتمل ہے اور اسلامی نماز کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کی تمام حرکات باوقار، باغرض اور با فائدہ ہیں اور اس میں وہ تمام طریق اختیار کئے گئے ہیں جومختلف اقوام میں اظہار ادب کے لئے استعمال ہوتے ہیں.ایرانی اقوام میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جانا اظہار ادب کی علامت ہے.ترکی نسل کی اقوام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا اظہار ادب کی علامت ہے.ہندوؤں اور بعض دوسری اقوام میں جھکنا اظہار ادب کی علامت ہے.ہندوستان اور افریقہ میں سجدے کے طور پر گر جانا اظہار ادب کی علامت ہے اور یورپین اقوام گھٹنے کے بل بیٹھ جانے کو اظہار ادب کی علامت سمجھتی ہیں.ہندو اور سکھ اب تو الگ ہو گئے ہیں پہلے وہ جب کبھی ملنے کے لئے آتے تھے تو خواہ انہیں کتنا بھی منع کرتے رہو وہ پیروں میں گر جاتے تھے.ایک سکھ جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقیدت تھی ایک دن میرے زمانہ خلافت کی ابتدا میں روتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کی جماعت نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے میں نے سمجھا کہ شاید کوئی لڑائی ہو گئی ہے او رکسی نے مارا ہے.میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں فوراً تحقیقات کروا کے سزا دوں گا آپ مجھے بتائیں کہ ہواکیا ہے.اس نے کہامیں بہشتی مقبرہ گیا تھا وہاں مرزا صاحب کی قبر پر سجدہ کر رہا تھا کہ احمدیوںنے پکڑ کر مجھے باہر نکال دیا.میں نے کہا یہ تو انہوں نے ٹھیک کیا.ہمارے مذہب میں یہ ناجائز ہے.وہ کہنے لگا میرا مذہب میرے ساتھ ہے اور آپ کا مذہب آپ کے ساتھ ہے میں جیسا چاہوں کروں ان کا کیا حق تھا کہ مجھے روکتے.غرض بڑی دیر تک اسے سمجھانا پڑا اور پھر کہیں اس کا غصہ فرو ہوا.اسی طرح افریقہ میں اظہار عقیدت کے طور پر سب لوگ سجدہ میں گر جاتے ہیں.ترکوں میں مَیں نے دیکھا ہے کہ جب وہ مثنوی رومی پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں.مغل بھی تعظیم کے لئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
Page 79
کھڑے ہو جاتے تھے.ایران میں سیدھا کھڑا ہو جانا اظہار ادب کی علامت تھا.غرض ہر قوم میں اظہار عقیدت کی کوئی نہ کوئی علامت مقرر ہے.مگر نماز ایک ایسا شعار ہے جس میں اسلام نے اس قسم کے تمام آداب کو جمع کر دیا ہے.اس کا فائدہ یہ ہےکہ یوں تو ایک مومن کو ساری نماز میں ہی لذّت آتی ہے مگر جب کوئی شخص اپنے قومی شعار میں پہنچے گا تو اسے کمال لذّت محسوس ہو گی.عیسائی تشہد کے وقت کو پسند کرتا ہے کیونکہ ان میں تشہد کا رواج ہے.ہندوستانی کو سجدے کی حالت میں بڑا تذلّل معلوم ہو تا ہے ایرانی کو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونے میں تذلّل معلوم ہوتا ہے.یہودی کو رکوع میں بڑا تذلّل معلوم ہو تا ہے.غرض جو قوم بھی اسلام میں داخل ہو تی ہے وہ اپنی روح کی تسکین اسلامی نماز میں پا تی ہے.دیکھو یہ کتنی بڑی خوبی ہے جو اسلام میں پائی جاتی ہے اس نے بتا دیا کہ اسلام میں ساری دنیا نے شامل ہو نا ہے.باقی قوموں کی عبادتوں میں یہ چیز اتنے لطیف طریق پر نظر نہیں آتی.پھر وضو کو لے لو.اسلام نےنماز سے پہلے وضو مقرر کیا ہے جو ایک نہایت اہم ذریعہ عبادت کی تکمیل کا ہے.تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ جب خیالات کا اجتماع ایک چیز پر ہوجاتا ہےتو اس کے مختلف حصوں سے جہاں اعصاب کے سرے ختم ہوتے ہیں NERVES ENDSاس کی طاقت ضائع ہو نی شروع ہو جاتی ہے اور خیالات میں پرا گندگی پیدا ہو جاتی ہے اگر پانی کا چھینٹا دیاجائے تو اعصاب کو سکون حاصل ہوکر خیالات مجتمع ہو جاتے ہیں.وضو کے ذریعہ سے انتشار خیالات کو روکا گیا ہے.پھر یہی نہیں کہ صرف وضو کا حکم دیا گیا ہے بلکہ نماز کے ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ نے نوافل بھی رکھ دیئےہیں.اسی طرح نماز کے بعد ذکر الٰہی کی تاکید ہے.اس طرح نہ صرف اس نے پہلے خیالات کو نماز میں پیدا ہونے سے روک دیا ہے بلکہ بعد میں آنے والے خیالات کو بھی ایک وقت تک دور رکھنے کی کوشش کی ہے.حقیقت یہ ہے کہ ہر کام وقت سے کچھ دیر پہلے شروع کر دیا جاتا ہے.مثلاً ہم نے دس بجے کی گاڑی سے جانا ہے تو آٹھ بجے سے ہی اس کا خیال آنا شروع ہو جائے گا.ہم روزہ رکھتے ہیں تو سورج غروب ہو نے سے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی ہم روزہ کھولنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں.یہی حال دوسرے کاموں کاہے یعنی پہلے کام کا اثر کچھ دیر تک چلا جاتا ہے اور اگلا کام کچھ دیر پہلے شروع ہوجاتا ہے.اس لحاظ سے اگر نماز سے پہلے وضو اور بعد میں نوافل وغیرہ نہ رکھے جاتے تو آدھی نماز تو پہلے خیالات میں ضائع ہو جاتی اور آدھی دوسرے خیالات میں.اس نقص کے ازالہ کے لئےخدا تعالیٰ نے پہلے وضو رکھا اور فرائض سے پہلے سنتیں اور نوافل رکھ دیئے.اسی طرح فرائض کے بعد کچھ سنتیں اور نوافل رکھ دیئے.اس طرح نماز کو اس نے دو دیواروں کے درمیان محفوظ کر دیا.اگر ان تدابیر کے ہو تے ہوئے پھر بھی کسی کی نماز ضائع ہو جائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہو گا.بہر حال خدا تعالیٰ نے انسان
Page 80
کے لئے اس بات کا موقع بہم پہنچا دیا ہے کہ وہ دنیوی خیالات سے علیحدہ ہوکر نماز ادا کرسکے اور اس نے عبادت کو شیطانی حملہ سے ہر ممکن طریق پر محفوظ کر دیا ہے.اس کے مقابل پر ہندو اور مسیحی عبادت گانے بجانے کانام ہے جو محض تلذّذ ہے عبادت نہیں یا چند بے معنی رسموں کا نام عبادت رکھ دیا گیا ہے.مثلاً آگ جلائی اور اس میں تیل ڈالا شعلہ نکلا اور منہ سے کوئی لفظ کہہ دیا اس سے قلب کی کیا صفائی ہو گی.سُبْـحَانَ اللہِ العَظِیْمِ کہنے سے تو دل کی صفائی کا تعلق نظر آتا ہے مگر آگ کا شعلہ نکلنے پر صاحا کہہ دینے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے.اسی طرح زردشتی نماز سورج اور پانی کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے اور بے شک وہ چند ادعیہ پر مشتمل ہے مگر مشرکانہ رنگ پکڑ گئی ہے اور یہودی نماز تو سجدہ سے ہی خالی ہے پھر وہ کسی اصل پر بھی مبنی نہیں.غرض اسلامی نماز میں (۱) سب ارکانِ ادب کو شامل کیا گیا ہے (۲) اسلام نے ایک قبلہ قائم کیا ہے جو اتحاد کے لئے ضرور ی ہے.دوسری قوموں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی.ہم یہ مانتے ہیں کہ جہاں اجتماعی دعا ہو تی ہے وہاں دوسری اقوام بھی کسی نہ کسی طرف منہ کر کے بیٹھتی ہیں.لیکن انہیں یہ احساس نہیںہوتا کہ دنیا کے سب لوگ ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ کام کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں میں سے افریقہ والے مشرق کی طرف منہ کرتے ہیںیورپ والے جنوب کی طرف منہ کرتے ہیں ایران والے شمال کی طرف منہ کرتے ہیں.ہندوستان والے مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں.اور ان کی حالت بالکل ویسی ہی ہو تی ہے جیسے ہندو لوگ ہَوَن کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں.وہ سب کے سب ایک ہی سمت کی طر ف منہ کر لیتے ہیں خواہ دنیا کے کسی گوشہ میں رہتے ہوں لیکن یہودی، عیسائی اور ہندو جدھر بھی چاہتا ہےمنہ کر لیتا ہے.کسی کامنہ شمال کی طرف ہوتا ہے تو کسی کا جنوب کی طرف، کسی کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے تو کسی کا مغرب کی طرف.کسی کی کرسی ادھر پڑی ہو ئی ہوتی ہے تو کسی کی اُدھر.پادری جب عبادت کرواتا ہے تو کچھ آدمی اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور کچھ اس کے بائیں طرف ہو تے ہیں.کچھ نمائندے اور مدد گار اس کے پیچھے کھڑے ہوجاتے ہیں.کوئی پانی لئے کھڑا ہوتا ہے توکوئی شمع ہاتھ میں لئے کھڑا ہو تا ہے.غرض انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں یک جہتی اور اتحاد رکھتے ہیں لیکن ساری دنیا کے مسلمانوں میں خواہ وہ شمال میں رہتے ہوں یا جنوب میں.مشرق میں رہتے ہوںیا مغرب میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ وہ ایک سمت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں.یہ ایک بہت بڑا اتحاد کا ذریعہ ہے بشرطیکہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں.مگر اس کے ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ قبلہ اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں رکھتا تاکہ شرک پیدا نہ ہو.وہ فرماتا ہے لِلّٰہِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَیْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ (البقرۃ: ۱۱۶)اللہ تعالیٰ کے لئے مشرق اور مغرب سب برابر ہیں جدھر منہ
Page 81
کرکے نماز پڑھو ادھر ہی تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے.غرض عبادت کو اس کمال تک اور کسی مذہب نے نہیں پہنچایا اور یہ اس کی فضیلت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے.(۳) پھر اسلامی عبادت میں جماعت کا اصل قائم کیا گیا ہے جو مذہب کی اصل غرض ہے.ظاہر ہے کہ انسانی زندگی دو پہلوؤں پر مشتمل ہے انفرادی اور اجتماعی، مذہب، سیاست، قومیت، اخلاق، تمدن تمام امور میں ان دونوں پہلوؤں کا خیال رکھنا ضروری ہو تا ہے ورنہ انسانی سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے.جن اقوام نے مثلاًسیاست میں اجتماعی زندگی اورذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھاوہ کمزور ہو گئی ہیں اسی طرح جن اقوام نے انسان کو محض مشین سیاست کا ایک پرزہ تجویز کر دیا ہے انہوں نے بھی انسانی ترقی کے راستوںکو مسدود کر دیا ہے جیسا کہ کمیونسٹ جماعت ہے.اصل اور کامیاب طریقہ یہی ہے کہ انفرادیت اور اجتماعیت دونوں کو ایک وقت میں اور توازن کے ساتھ قائم رکھا جائے.مذہب میں بھی یہی طریقہ کامیاب اور مفید ہو سکتا ہے اور اسلام ہی ہے جس نے کہ اس طریقہ کو مدّ ِنظر رکھا ہے اور تمام مذاہب میں سے پہلی دفعہ مذہب میں اجتماعی روح کو ایک مقرر اور معزز مقام عطا کیا ہے.مثلاً نماز ہےیوں تو جیساکہ میں نے بتایا ہے دوسری قوموں کے لوگ بھی عبادت کے لئے جمع ہو تے ہیں.عیسائی گرجوں میں ہندو مندروں میں اور سکھ گوردوارو ں میں.لیکن وہ جماعتی رنگ جو اسلام کی نماز میں پایا جاتا ہے وہ دوسری قوموں میں نہیں.پھر ان کے نزدیک جماعت فرض نہیں یہ نہیں کہ جو شخص عبادت کے لئے جماعت میں شامل نہ ہو گناہ گار ہو جاتا ہے.لیکن اسلام میں نماز باجماعت کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس میں سوائے معذوروں کے سب کا آنا ضروری قرار دیا گیا ہے.آج بے شک مسلمانوں میں الحاد پیدا ہو گیا ہے اور وہ نماز کے لئے مسجدوں میں نہیں آتے لیکن سوال ان کے عمل کا نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کا ہے اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ نماز با جماعت فرض ہے اور ہر مسلمان باوجود اپنی عملی کمزوریوں کے یہ تسلیم کرتا ہے کہ نماز با جماعت فرض ہے.پس اسلامی عبادت اور دوسرے مذاہب کی عبادات میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اسلام نے باجماعت نماز فرض قرار دی ہے جبکہ دوسرے مذاہب نے اسے فرض قرار نہیںدیا یہ امر ان کی مرضی پر منحصر ہو تا ہے کہ وہ عبادت کے لئے آئیں یا نہ آئیں.پھر ہماری نماز اتنےاوقات میں مقرر ہے کہ دوسرے مذاہب میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی مثلاً(۱) سورج نکلنے سے پہلے نما ز ہے (۲) زوال کے بعد نماز ہے (۳) سورج کے غروب کے قریب نماز ہے (۴) سورج کے غروب ہو نے کے بعد نماز ہے (۵) رات کو سو نے سے پہلے نماز ہے اور یہ پانچ نمازیں فرض ہیں.یہ نہیں کہ ان کی ادائیگی کسی کی مرضی پر منحصر ہو اس قدر عبادت اور پھر با جماعت عبادت اوروں میں کہاں پائی جاتی ہے.اس وقت مسلمان بے دین ہو چکے ہیں لیکن اب بھی جو
Page 82
تھوڑے بہت مسلمان مسجد و ں میں آتے ہیں ان کی نمازوں کو اگر جمع کیا جائے اور وہ عیسائیوں پر دس سال میں پھیلادی جائیں تو تمام عیسائیوں نے دس سال میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی جتنی مسلمانوں نے ایک سال میں پڑھی ہوں گی.مثلاً سو میں سے اگر پانچ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کے معنے یہ ہیں کہ چالیس کروڑ میں سے دو کروڑ مسلمان روزانہ نما زپڑھتے ہیں یہ دو کروڑمسلمان دس کروڑ نمازیںروزانہ ادا کرتے ہیں ہفتہ میں ستر کروڑ نمازیں ہوئیں اور پھر یہ ستر کروڑ نمازیں وہ ہیں جو باجماعت ہیں.عیسائیوں میں صرف دو چار فیصدی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ہندوستان میں تو یہ لوگ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں عموماً وہ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں لیکن یورپ میں یہ دو فیصدی بھی نہیں ہو تے.بڑےبڑے گرجوں میں صرف پانچ پانچ چھ چھ آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور عبادت کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کی اوسط بھی پانچ فیصدی فرض کی جائے تب بھی پانچ فیصدی عیسائیوں کی ہفتہ میں صرف پانچ نمازیں ہو تی ہیں.اس کے مقابلہ میں صرف ایک مسلمان ہفتہ میں ۵x۷ نمازیں پڑھتا ہے یعنی پانچ پانچ روزانہ اور ہفتہ میں پانچ فیصدی مسلمانوں کی نمازیں ۱۷۵ ہو جاتی ہیں.یہ کتنا بڑا فرق ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کی نماز میں پایا جاتا ہے کہ پانچ فیصدی عیسائی ہفتہ میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور پانچ فیصدی مسلمان ہفتہ میں ۱۷۵ نمازیں پڑھتے ہیں.گویا مسیحیوں کی تعداد اگر مسلمانوں کےبرابر ہو اور مسیحی گرجوں میں اتنے فیصدی جاتے ہوں جتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں گو ایسا نہیں ہے تو پھر بھی مسلمان مسیحیوں سے ۱۷۵ گنے زیادہ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں.پھر ہندوؤں میں تو اتنا بھی نہیں.زردشتیوں میں پادری جاتے ہیں اور سمندر کے کنارے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں.پس اسلام نے جو نماز مقرر کی ہے اس کے مقابلہ میں دوسرے تمام مذاہب کی نمازیں ہیچ ہیں.عیسائیوں میں تواب ہفتہ والی نماز بھی نہیں رہی.پادری اعلان کرتے ہیں کہ فلاں دن گرجا میں گانا ہو گا اور گانے کی خاطر کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں لیکن مسلمانوں میں امام خاموشی کے ساتھ مسجد میں آجاتا ہے، نماز پڑھنے والے بھی آجاتے ہیں اور جماعت ہو جاتی ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں مسلمانوں میں سے اکثر اب نمازیںنہیں پڑھتے مگر پھر بھی دوسروں کے مقابلہ میں ان کی نسبت کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے.پس اسلام نے جماعت کا جو اصل قائم کیا ہے اور جس کے ذریعہ اسلا م نے قومی اجتماع کی صورت پیدا کی ہے اس کی دنیا میں اور کہیں مثال نہیں ملتی.پھر اس کے ساتھ اسلام نے یہ شرط بھی رکھ دی ہےکہ اگر اپنے محلہ میں ہو تو اپنے محلہ کی مسجد میں نمازیں پڑھو.دوسرے مذاہب میں یہ بات نہیں بلکہ جس گرجا میں چاہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس طرح دوسرے ہمسائیوں اور خود امام نماز سے اختلاف کی روح نمازوں تک میں پیدا ہو جاتی ہے لیکن اسلام نے جماعت میں جو فوائد ہو سکتے ہیں ان
Page 83
کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے.روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابیؓ سے کسی نے کہا کہ چلو فلاں محلہ میں جا کر نماز پڑھیں.اس صحابی ؓ نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے محلہ کی مسجد میں نماز ادا کرنی چاہیے.اس لئے میں تو اپنے ہی محلہ کی مسجد میں نماز ادا کروں گا.پس اسلام کہتا ہے کہ سوائے اس کے کہ کوئی جلسہ کسی دوسری مسجد میں ہو رہا ہو یا وعظ ونصیحت کا کوئی خاص موقعہ میسر آئے اپنے محلہ کی مسجد میں نمازیں ادا کرو.یہ چیز عیسائیوں میں نہیں، پارسیوں میں نہیں، زردشتیوںاور سکھوں میں نہیں.ادھر ادھر چلے جانے سے جماعت نہیں بنتی اور نہ نماز باجماعت کی جو غرض ہے وہ پوری ہو تی ہے.ایک مسلمان اگر اپنے محلہ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تو فوراً پکڑا جائے گا.اگر وہ کہے گا کہ میں فلاں مسجد میں نما زیں پڑھتا ہوں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم وہاں نمازیں کیوں ادا کرتے ہو.تم اس محلہ میں رہتے ہو.اور اسی میں تمہیںنمازیں ادا کرنی چا ہئیں.اس کے بعد اگر تحقیق کی جائے گی تو کوئی نہ کوئی بات ضرور نکل آئے گی.مثلاً ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ مجھے اس مسجد کے امام سے ناراضگی ہے.اس صورت میں پھر جماعت اور نظام کا فرض ہو گا کہ وہ اس مناقشت کو دور کرے اور اس طرح پھر قومی جتھہ قائم ہوجائے گا.بہرحال یہ اسلام کی ایک ایسی خوبی ہے جس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں.(۴) پھر اسلامی نماز میں اللہ تعالیٰ نے صفات الٰہیہ پر غور کرنے کا رستہ کھول دیا ہے.مسلمان اپنی نمازمیں روزانہ قرآن کریم پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے رکوع و سجود میں دعائیں کرتا ہے.سورۃ فاتحہ کے کلمات رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اس کے سامنے آتے رہتے ہیں اور وہ ان پر غور کرتا ہے.عیسائیوں میں ایک مقررہ دعا ہے جو پادری پڑھ دے گا مگر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ خود پڑھیں.اس طرح اسلام نےصفات الٰہیہ پر فکر کا راستہ کھو ل دیا ہے.(۵) اسلامی نماز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لقاء کا ایک ذریعہ بنایا ہے.اللہ اکبر کہہ دینے کے بعد گویا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے.وہ کسی سے بات نہیں کرتا.مگر گرجوں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی آجائے تو سب اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہماری نماز میں ادھر اُدھر جھانکنا منع ہے.نماز پڑھنے والے کلّی طور پر عبادت میں محوہو جاتے ہیں دوسرے کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے.حتی کہ باہر والے کا بھی حق نہیں ہوتا کہ نمازی کی غلطی پر اس کو توجہ دلائے.مثلاً کوئی نمازی ایک سجدہ زیادہ کر دے یا کم کر دے تو ایک ایسا آدمی جو نمازمیں شامل نہیں اسے اس غلطی پر آگاہ نہیں کر سکتا.گویا ایک مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے اور کسی باہر والے کا یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اس کے کام میں دخل دے ہاں وہ شخص غلطی نکال سکتا ہے جو اس
Page 84
کے ساتھ جماعت میں شامل ہو.اسی طرح وہ ادھر اُدھر جھانک بھی نہیں سکتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو نمازی ادھر ادھر دیکھے گاخدا تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر بنا دے گا.اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کی حماقت کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ ایسا شخص اوّل درجہ کا احمق ہو تا ہے.وہ نماز میں ادھر اُدھر کیوں دیکھتا ہے.اسی لئے کہ اسے کوئی عجیب چیز نظر آتی ہے.مگر سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جیسی عجیب چیز اور کون سی ہے اور اگر وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور چیزوںکو دیکھتا ہے تو وہ یقیناً گدھا ہے.اس کے سامنے خدا تعالیٰ جیسا حسین چہرہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے بلی یا چوہے کو.تو اس کے گدھا ہو نے میں کیا شک ہے.پس اسلامی نماز لقاء الٰہی کا ایک زبردست ذریعہ ہے.مگر دوسرے مذاہب کی نمازوں میں لقاء الٰہی والی صورت ہی نہیں.گرجامیں پادری نماز پڑھا رہاہوتا ہے تو اس کا کوئی ساتھی لیمپ اٹھائے ہوئےہوتا ہے، کوئی پانی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی اور کاموں میں مشغول ہوتا ہے.مگر نماز ان سب کی ہو جاتی ہے لیکن اسلامی نماز میں کلام کرنا اور ادھر ادھر دیکھنا منع ہے جو دوسرے مذاہب کی نمازوں میں منع نہیں.اسلامی نماز اور دوسرے مذاہب کی نماز وں میں فرق شروع میں صحابہ کرامؓ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نماز میں بول لیا کرتے تھے کیونکہ ابھی وہ اسلامی نقطہ نگاہ سےپوری طرح واقف نہیں ہوئے تھے.نماز پڑھتےہوئے اگر کوئی آجاتا تو وہ نماز پڑھنے والے سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ اب کون سی رکعت ہے اور وہ اسے بتادیتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے منع فرمایا.چنانچہ اسلام کے رو سے باہر سے آنے والے کے السلام علیکم کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں.کسی کا باپ آجائے، بھائی آجائے، بچہ آجائے، افسر آجائے یا کوئی اور عزیز آجائےاور وہ السلام علیکم کہے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا.وہ تو اس دنیا میں نہیں ہو تا اس دنیا میں ہو تو جواب دے وہ تو خدا تعالیٰ کے سامنے چلا گیا جواب کیا دے.یہی وجہ ہے کہ جب ہم نما ز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں جس کے معنے یہ ہیں کہ اے میرے بھائیو اور میرے عزیزواور شتہ دارو ! تم بھی مجھے عزیز ہو مگر تم سے زیادہ مجھے خدا تعالیٰ عزیز ہے میں اس کے سامنے جاتا ہوں اور تم سے قطع تعلق کرتا ہوں.جب نماز ختم ہو تی ہے تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اب واپس آگیاہوں جیسے کوئی باہر سے آنے پر السلام علیکم کہتا ہے اسی طرح وہ بھی کہتا ہے میں باہر گیا ہوا تھا اب واپس آگیا ہوں.یہ کتنی خالص اور مکمل نماز ہے.اسلامی نماز کی دعاؤں کے لحاظ سے فضیلت (۶) نماز کے ذریعہ اسلام نے دعا کا رستہ کھولا ہے.
Page 85
دعائیں دو قسم کی ہو تی ہیں (۱) مقررہ اور (۲) مرخّصہ.مقررہ میں اعلیٰ درجہ کی دعائیں شامل ہیں جن کو ممکن تھا ہم دعا کرتے وقت چھوڑ دیتے اور مرخّصہ وہ ہیں جو ہم اپنی ضرورتوں کے لئے اپنی زبان میں کر سکتے ہیں.ممکن تھا کہ ہم بعض ضرور ی اور اہم دعاؤں کو چھوڑ دیتے یا وہ ہمارے ذہن میں نہ آتیں سو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے خود مقرر کر دیں مثلاً اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ سے الضَّآلِّيْنَ تک جو دعا ہے وہ ہمارے ذہن میں نہ آسکتی تھی یا سَمِعَ اللّٰہُ لِمَنْ حَمِدَہٗ.رَبَّنَا لَکَ الْحَمْدُ وغیرہ کلمات ہیں.یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے ان کو تو خدا اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا اور باقی اگر ہمارا مالی نقصان ہو جائے، ملازمت میں خرابی واقع ہوجائے، تجارت میں ترقی نہ ہو یا اور کوئی ضرورت درپیش ہو تو اس کے لئے اپنی زبان میں اور اپنی ضروریات کے مطابق دعائیں مانگنےکی اجازت دے دی.اس رنگ کی انفرادی یا قومی طور پر دعائیں دوسری قوموں کی عبادتوں میں نہیں پائی جاتیں.اسلامی نماز میں قرأت بالجہر اور قرأت بالسِّر (۷) قرأت بالجہر اور قرأت بالسِّر بھی اسلامی نماز کی ایک خصوصیت ہے.عیسائیوں کو دیکھو تو پادری وعظ کر دے گا.بائبل کی ایک آیت کو لے لے گا اور اسی پر تقریر کر دے گا اور یہ ان کا گرجا ہو جائےگا.اس کے بعد وہ اپنی مقررہ دعائیں کر لیں گے.اے خدا تو مجھے کل کی روٹی آج دے دے یا اے خدا جس طرح تیری بادشاہت آسمان پر ہے ویسی ہی زمین پر بھی قائم ہو(متی باب نمبر۶ آیت ۱۰،۱۱).اس قسم کی چند مقررہ دعائیں ہیں جو وہ کرتے ہیں.مگر اسلام نے نمازو ںکو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے (۱)بالجہر اور (۲) بالسِّر.اسی طرح بعض حصے ایسے ہیں جن میں امام قرأت بالجہر سے کام لیتا ہے اور ہم اس کے پیچھے وقفوں میں بالسِّر بھی پڑھتے ہیں.مثلاً سورۂ فاتحہ اور بعض حصے ایسے ہیں جن میں صرف امام پڑھتا ہے ہم اُسےدہراتے نہیں.خاموشی سے سنتے ہیں جیسے تلاوت قرآن.پھر امام کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو زیادہ متقی ہو وہ امام بنے.اب یہ لازمی بات ہے کہ جب زیادہ متقی انسان نماز پڑھائے گا تو اس کے اندر جو سوز اور درد ہو گا اس کا دوسروں پر بھی اثر پڑے گا اور ان میں بھی تبدیلی پیدا ہو تی چلی جائے گی.حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ راولپنڈی میں ایک مؤذن تھا اس کی آواز بہت سریلی تھے.مسجد کے پاس ہی ایک سکھ رہتا تھا ایک دن اس سکھ کی لڑکی کہنے لگی باپو جی میں تو مسلمان ہو جاؤں گی.باپ نے پوچھا تم نے اسلام میں کیا دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی اس مذہب میں بہت سچائی ہے.مؤذن اذان دیتا ہے تو اس میں ایسادرد ہو تا ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت پر دلالت کرتا ہے وہ سکھ رئیس آدمی تھا اس نے مؤذن کو کسی اور کا م پر لگا دیا.مثلاً ً پہلے اگر وہ پندرہ روپے لیتا تھا تو اب اس نے کہا اچھاتم پچیس روپے لے لو اور میرے فلاں کام پر چلےجاؤ.چنانچہ وہ چلا گیا اور کوئی دوسر امؤذن
Page 86
آگیا اس کی آواز اتفاقاً اچھی نہ تھی.چند دنوں کے بعد باپ نے پوچھا بیٹی اب اسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگی اب مجھے اسلا م کی طرف کوئی رغبت نہیں رہی اور میری سمجھ میں یہ بات آگئی ہے کہ مسلمانوں میں اچھے آدمی بھی ہوتے ہیں اور برے بھی.جیسے ہمارے سکھوں میں اچھے بھی ہو تے ہیں اور برے بھی پس امامت کے ذریعہ جب ہم زیادہ اتقٰی انسان کی سوز کی آواز سنیں گے توہمارے اندر زیادہ سوز پیدا ہو گا اور اس طرح دعا کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائیں گے.(۸)پھر امامت کے لئے اسلام نے کسی خاندان یا کسی خاص قوم کی خصوصیت نہیں رکھی.عیسائیوں میں مقررہ ORDAINEDپادری کے سوا کوئی دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا ہندوؤں میں خاص نسل کے پنڈت کے سوا کوئی دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا.سکھوں میں گرنتھی کے سوا کوئی دوسرا آدمی گرنتھ صاحب کا پاٹ نہیں کرا سکتا.لیکن اسلام نے کسی خاص گروہ میں سے ہو نے کے اصول کو توڑدیا ہے.اس کے نزدیک ہر انسان جو دیندار ہو امام بن سکتا ہے اس کے لئے کسی خاص نظام، کسی خاص نسل یا کسی خاص خاندان میں سے ہونا ضروری نہیں.یوروپین لوگ جب ادھر آتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی اس خصوصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہو تے ہیں.ان میں سے جب تک کسی کے پاس سند نہ ہو نماز نہیں پڑھا سکتا.لیکن مسلمانوں میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک کو امامت کا حقدار بنا کر اپنے دربارمیں مساوات کو قائم کر دیا ہے اور سند صرف تقویٰ کی رکھی ہے.اسلامی نماز میں مساوات پھر اسلامی مساجد میں نماز ادا کرتے وقت کسی قومی یا نسلی امتیاز کا لحاظ نہیں رکھا جاتا.انگریزوں کے گرجوں میں جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوا ہو تا ہے کہ یہ جگہ فلاں خاندان کے لئے مخصوص ہے.یہ جگہ فلاں لاٹ صاحب کے لئے ہے(کیونکہ وہ مثلاً پچیس پاؤنڈ سالانہ چندہ گرجا کو دیتے ہیں ) فلاں جگہ فلاں کی ہے اور فلاں جگہ فلاں کی ہے گویا خدا تعالیٰ کی عبادت گاہ بھی بکتی ہے.یہی حال دوسری قوموں کا ہے.بڑے آدمیوں کے لئے اچھی جگہ رکھی جاتی ہے.پاٹ ہو رہا ہے، پنڈت بول رہا ہے، گرنتھی گرنتھ پڑھ رہا ہے تو ایک بڑے آدمی کو دیکھ کر وہ فوراً بول اٹھتا ہے.سردار صاحب آگئے.سردار جی یہاں تشریف لایئے.لیکن مسلمانوں میں اگر کوئی ایسا کرے تو سب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور کہیں گے جاؤ تمہاری نماز باطل ہو گئی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمانوں میں دولت بڑھ گئی اور غرور آنا شروع ہوا تو بادشاہ ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ جب حج کے لئے جاتے تو پہلے ان کا نوکر آکر مسجد میں ان کا مصلّٰی بچھا دیتا ایک دفعہ بادشاہ کا مصلّٰی بچھاہوا تھا کہ ایک غریب آیا اور اس پر کھڑا ہو گیا.سپاہی نے کہا یہ بادشاہ کا مصلّٰی ہے اس پر تم کیوں کھڑے ہوئے
Page 87
ہو.اس نے جواب دیا یہ بادشاہ کا دربار نہیں.اس دربار میں ہم سب برابر ہیں.جب سپاہی نے زیادہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو سارے نمازی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ بڑے بادشاہ یعنی خدا تعالیٰ کا دربار ہے اس میں دنیاوی بادشاہ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک نوکر کی ہے کمزور بھی یہاں ایسا ہی ہے جیسا طاقتور ہے.مسجد میں ایک ہنگامہ برپاہو گیا اور آخر بادشاہ کو بھی جھکنا پڑا.چنانچہ اب وہاں باہر ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں بادشاہ نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نہیں گھستے کیونکہ اگر وہ مسجد میں جائیں تو انہیں وہاں دوسروں کے برابر کھڑا ہو نا پڑتا ہے.آج تک کئی اسلامی حکومتیں گذری ہیں مگر وہ کسی پر پابندی نہیں لگا سکیں.کوئی دھوبی ہو، نائی ہو، کمہار ہو، اسے بادشاہ کے پاس کھڑا ہو نے سے کوئی شخص روک نہیں سکتا بلکہ بادشاہ تک نہیں روک سکتا پس جہاں اسلام نے امامت کے متعلق کہہ دیا کہ سب مسلمان اس حق میں مسا وی ہیں وہاں یہ قانون مقرر کر کے کہ مسجد میں ہر ایک برابر کا حقدار ہے انسانوںمیں مساوات قائم کر دی.اسلامی نماز کے ادا کرنے کے لئے کسی خاص جگہ کی قید نہیں (۹) پھر اسلام نے ایک اور حد بندی بھی توڑ دی عیسائی نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ گرجے میں جائے گا، ہندو نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ مندر میں جائےگا، سکھ نے اگر نماز پڑھنی ہو تو وہ گوردوارہ میں جائے گا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ لِیَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا.(بخاری کتاب الصلٰوۃ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم جعلت لی الارض) میرے لئے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے عیسائیوں میں صرف گرجوں میں عبادت ہو تی ہے.ہندوؤں میں صرف مندروں میں عبادت ہوتی ہےمگر ساری زمین کے چپہ چپہ پر صرف مسلمان نے سجدہ کیا ہے.ہم جب پہاڑوں پر جاتے ہیں تو جان بوجھ کر مختلف جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں خدا تعالیٰ کی عبادت نہ کی گئی ہو.دیکھو کتنی وسعت ہے جو اسلام میں پائی جاتی ہے جہاں خدا تعالیٰ نے امامت میں ہر ایک کو حقدار بنا کر اپنے دربار میں مساوات قائم کر دی.جہاں مسجدوں میں ہر ایک کو برابر کا حقدار بنا کر انسانوں میں مساوات قائم کر دی وہاں جُعِلَتْ لِیَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا کہہ کر زمین کے چپہ چپہ میں مساوات قائم کردی.(۱۰) پھر ایک طرف جہاں جُعِلَتْ لِیَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا کہہ کر اس نے ساری زمین کو مسجد میں تبدیل کر دیا وہاں فرائض کے ساتھ نوافل ملا کر اس نےہر گھر کو مسجد بنا دیا.کیونکہ نوافل کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا ہے کہ وہ گھر میں پڑھے جائیں.جیسے فرمایا لَا تَـجْعَلُوْا بُیُوْتَکُمْ مَقَابِرَ(مسلم کتاب الصلٰوۃ المسافرین باب استحباب صلٰوۃ الـنـافلۃ).اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ.یعنی جیسے مقابر پر نماز پڑھنی جائز نہیں
Page 88
اسی طرح تم گھروں کو بھی مت سمجھو.بلکہ کچھ نمازیں مسجد میں ادا کیا کرو اور کچھ گھروں میں ادا کیا کرو.اس طرح خدا تعالیٰ نے چپہ چپہ زمین پر عبادت کے لئے رستہ کھول دیا.پھر علاوہ معین صورت کی عبادت کے جیساکہ میں نے بتایا ہے ایک عبادت غیر معین صورت میں بھی ہو تی ہے اور وہ ذکر و فکر ہے.یہ عبادت غیر معین صورت میں اس لئے رکھی کہ معین صورت کی نماز تو ہر وقت ادا نہیں ہو سکتی لیکن غیر معین صورت کی نماز ہر وقت ادا کی جا سکتی ہے.سوتے جاگتے، چلتے پھر تے ہر حالت میں ذکر ہو جاتا ہے.کسی شخص نے ایک بزرگ سے پو چھا کہ اگر ہم عبادت ہی کرتے رہیں تو ہم کام کیسے کریں؟ انہوںنے فرمایا دست درکار و دل با یار.اپنے کاموں کو بھی کرتے جاؤ اور ذکر الٰہی بھی کرتے رہو.پیشے کرو، تجارتیں کرو، دوسرے دنیوی کاروبار کرو مگر ساتھ ہی خدا تعالیٰ کو بھی یاد کرتے جاؤ.حضرت مظہر جان جاناں ؒ ایک بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں.آپ شاعر بھی تھے آپ کے ایک شاگرد میاں غلام علی تھے جو آپ کےبہت مقرب مرید تھے ایک دن آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی شخص آیا اور آپ کے لئےبالائی کے لڈو تحفہ کے طور پر لایا.آپ کو بالائی کے لڈو بہت پسند تھے.حضرت مظہر جان جاناں ؒ نے ان میں سے دو لڈو اٹھا کر اپنے شاگر میاں غلام علی کو دے دیئے اور کہا تمہیں بھی یہ پسند ہوں گے بڑے مزیدار ہو تے ہیں.اس لئے یہ دو لڈو تم بھی لے لو.تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا.میاں غلام علی تم نے وہ لڈو کیا کئے؟ میاں غلام علی نے کہا حضور میں نے وہ کھا لئے.آپ نے فرمایا اتنی جلدی کھا لئے؟ میاں غلام علی نے کہا وہ چیز ہی کیا تھے ایک ہی دفعہ منہ میں ڈالے اور گھل گئے.آپ نے حیرت سے پوچھا اچھا وہ دونوں لڈو تم نے کھا لئے معلوم ہو تا ہے تمہیں لڈو کھانے نہیں آتے.انہوں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے کہ لڈو کس طرح کھائے جاتے ہیں.آپ نے فرمایا اچھا پھر کسی دن لڈو آئےتو میں تمہیں لڈو کھانے سکھاؤں گا.چوتھے پانچویں دن پھر کوئی اور مرید لڈو لے آیا اور میاں غلام علی نے حضرت مظہر جان جاناں ؒ سے کہا کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہیں لڈو کھا نے سکھاؤں گا اب لڈو کھانا سکھا دیجئے.حضرت مظہر جان جاناںؒ اور حضرت ولی اللہ شاہ صاحب ؒ کو صفائی کا خاص طور پر بہت خیال رہتا تھا.حضرت ولی اللہ شاہ صاحبؒتو ہر روز دھلوا کر نیا جوڑا پہنا کرتے تھے.جب دہلی کا بادشاہ آپ کا مرید ہوا تو وہ روزانہ آپ کو ایک نیا جوڑا سلوا کر بھیجا کرتا تھا.حضرت مظہر جان جاناں ؒ بھی بڑی نفیس طبیعت کے تھے.کسی چیز کو ٹیڑھی پڑی ہوئی دیکھ کر آپ غصہ میں آجاتے.آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے اس کو ٹیڑھا رکھا ہے اس کا دل کیسے صاف ہو گا.ایک دفعہ آپ کے پاس ایک بادشاہ ملاقات کے لئے آیا.اس کے وزیر کو پیاس لگی اس نے آبخورہ اٹھایا اور پانی پی لیا.پانی پی کر اس نے
Page 89
آبخورہ الٹا رکھ دیا.حضرت مظہر جان جاناںؒکو یہ دیکھ کرسخت غصہ آیا اور انہوں نے بادشاہ سے فرمایا آپ نے کیسا بے وقوف وزیر رکھا ہوا ہے جسے آبخورہ بھی سیدھا رکھنا نہیں آتا.غرض آپ کو صفائی کا بہت خیال رہتا تھا.آپ نے جیب سے رومال نکالا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اسے فرش پر بچھایا.پھر اس پر دو لڈو رکھے اور ایک لڈو سے چھوٹا سا ٹکڑا لیا، منہ میں ڈالا اور سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگ گئے.پھر فرمایا میاں غلام علی کیا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ لڈوکیسے بنا.مظہر کی حیثیت ہی کیا تھی.ذلیل پانی سے پید اہوا، پھر لوتھڑا بنا، گوشت پوست بنا اور آخر ایک دن یہ فنا ہو جائے گا.لیکن خدا تعالیٰ کو دیکھو عرش پر بیٹھا ہوا ہے اس نے ہر چیز کو پید اکیا، زمین کو بھی پیدا کیا، آسمان کو بھی پیدا کیا اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو بھی اس نے پیدا کیا.ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے.اگلے پچھلے علوم اسے حاصل ہیں.جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس نے خیال کیا کہ مظہر ایک دن پیدا ہو گا اور بالائی کے لڈو اسے اچھے لگیں گے.اس لئے ہم اس کے لئے بالائی کے لڈو تیار کروائیں.میاں غلام علی کیا تم نے کبھی سوچا کہ پھر اس نے کہاں سے میٹھا پیدا کیا.اس نے زمیندار کے دل میں خیال پیدا کیا اس نے گنا بویا پھر شکر بنی اور سینکڑوں آدمیوں کو اس نے اس کام میں لگا دیا.محض اس لئے کہ مظہر جان جاناںؒایک لڈو کھا لے.غرض اسی طرح ایک ایک کر کے تفصیلات بیان کیں اور پھر فرمایا.بالائی کو دیکھو جانور نے کیا کیاکھایا اس سے دودھ بنا دود ھ سے بالائی تیار ہوئی.پھر بالائی اور میٹھے سے حلوائی نے لڈو تیار کئے اور اس لئے کئے تا کہ مظہر جان جاناںؒایک لڈو کھالے.آپ اسی رو میں بہے جا رہے تھےاور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کر رہے تھے کہ اذان ہو گئی اور آپ نماز کے لئے تشریف لے گئے اور لڈو وہیں پڑا رہ گیا.(حکایات اولیاء صفحہ ۳۰تا۳۳) غرض اگر ہم نمازیں ہی پڑھتے رہیں تو دوسرے کام کس طرح کر سکتے ہیں.وعظ و نصیحت بھی کرنا ہو تا ہے.دنیا کے دوسرے کام بھی کرنے ہو تے ہیں.لیکن ذکر ہر وقت ہو سکتا ہے.ایک روٹی پکانے والا روٹی پکاتا جائے اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہتا جائے تو اس کا کیا حرج ہے، پیڑا بنائے اور سبحان اللہ کہے آٹا پھیلاکر کپڑے پر لگائے تو سبحان اللہ کہے تنور میں لگائے تو سبحان اللہ کہے،سیخ کے ساتھ روٹی ہلائے تو سبحان اللہ کہے، روٹی کو نکالے تو سبحان اللہ کہے، اس طرح روٹی بھی پک جائے گی اور ذکر الٰہی بھی ہو تا رہے گا.بجائے باتیں کرنے کے اگر وہ اس کام میں لگ جائے تو اس کا کیا حرج ہے یا مثلاً چکی پیسنے والی عورت ہے وہ چکی بھی پیستی جائے اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لاحول ولاقوۃ اِلّا باللہ یا جو ذکر بھی مناسب ہو کرتی جائے تو آٹا کم نہیں ہو جائے گا.یا یہ ذکر کرنے سے آٹا خراب نہیں ہو جائے گا ڈاکٹر اپریشن کرتا جائے اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتا جائے اور غور کرے کہ خدا تعالیٰ نے انسانی جسم میں کیسا عظیم الشان نظام قائم کیا ہوا ہے.
Page 90
اسی طرح ہر پیشے والا تسبیح کو بھی جاری رکھ سکتا ہے اور اپنا کام بھی کر سکتا ہے لیکن نمازیں ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتیں.ہم کھڑے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تیر رہے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، بندوق سے نشانہ کر رہے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، موٹر چلا رہے ہوں تب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں.مگر اس قسم کا ذکر اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں نہیں.ہندو کو کہو کہ وہ اپنی کتاب سے نکالے، زردشتی کو کہو کہ وہ اپنی کتاب سے نکالے.تمہیں اس قسم کے ذکر کا دوسرے مذاہب میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ملے گا.غرض خدا تعالیٰ نے اس طرح عبادت کے راستے کھول دیئے ہیں کہ اگر کوئی دیانت دار ہو تو وہ مجبور ہے کہ ذکر الٰہی کرے.اسلامی ذکر اور اس کے لحاظ سے اسلامی عبادت کی فضیلت (۱) سب سے بڑا ذکر تو بسم اللہ ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو اس کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو.بسم اللہ کے بغیروہ کام بے برکت ہو جائے گا.انسان کپڑے پہنے تو پہلے بسم اللہ کہے، جوتی پہنے تو پہلے بسم اللہ کہے، پانی پیئے تو پہلے بسم اللہ کہے، برتن مانجے تو پہلے بسم اللہ کہے، جانور ذبح کرے تو پہلے بسم اللہ کہے، گوشت پکائے تو پہلے بسم اللہ کہےغرض ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہے.بسم اللہ میں اس طرف اشارہ ہو تا ہے کہ دنیا میں جس قدر چیزیں پائی جاتی ہیں یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی مِلک ہیں او رمیں اس کی اجازت کے ماتحت ان کو اپنے استعمال میں لا رہا ہوں.مثلاً جانور ذبح کرتے وقت جب وہ بسم اللہ کہتا ہے تو اس کے معنے یہ ہو تے ہیں کہ یہ جانور میں نے کسی سے چھینا نہیں.اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اس نے مجھے کہاہے کھالو.اس لئے میں اسے ذبح کرتا ہوں پھر مرچ ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، کوئلہ ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، برتن ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے ہیں.میں تو مستعار طور پر اس کی ملکیتی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں.حضرت سید عبد القادر جیلا نیؒ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا کھاتے تھے اور اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے تھے.بعض لوگوں نے آپ پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں جب تک خدا تعالیٰ مجھے نہیںکہتا.اے عبد القادر جیلانیؒ تجھے میری ذات ہی کی قسم تو کھا اس وقت تک میں نہیں کھاتا.اور جب تک خدا تعالیٰ مجھے یہ نہیں کہتا کہ اے عبد القادر جیلانیؒ تجھے میری ذات ہی کی قسم تو فلاں کپڑا پہن تب تک میںکپڑا نہیں پہنتا(خزینۃ الاصفیاء شیخ عبد القادر جیلانی جلد ۱ صفحہ ۱۶۰).سید عبد القادر جیلانیؒ کو تو خدا کہتا ہو گا کہ تو ایسا کر مگر ہر مسلمان جب کسی کام کے کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہی ایسا کہتا ہے.پس ہر مسلمان ہی درحقیقت ہر کھانا خدا تعالیٰ کے حکم سے کھاتا ہے اور ہرکپڑا اس کے حکم سے پہنتا ہے.
Page 91
(۲) دوسرا ذکر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ہےجو ہر کام کے ختم ہو نے پر کہا جاتا ہے.قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (یونس:۱۱) مومنوں کا آخری قول یہی ہو تا ہے کہ سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے.(۳) تیسرا ذکر سُبْحَانَ اللّٰہِ ہے جو ہر تعجب انگیز اور بڑے کام پر کیا جاتا ہے.اگر اس پر بھی غور کیاجائے تو یہ ذکر اپنے اندر بڑی حکمتیں رکھتا ہے.(۴) پھر مصیبت کے اوقات کے لئے اسلام نےیہ ذکر سکھایا کہ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ یعنی جب تم پر کوئی مصیبت آئے تم اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کہو جس کے معنے یہ ہیں کہ ہم اسی کے ہیں اور بالآخر ہم نے بھی اسی کی طرف جانا ہے اگر کوئی عزیز مجھے مل گیا تھا تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا اور اب جبکہ اس نے واپس لے لیا ہے میرے لئے غم کی کون سی بات ہے.پھر اگر کوئی گلاس ٹوٹ گیا تو کہہ دیا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ یہ گلاس بھی آخر خدا تعالیٰ نے ہی دیا تھا ہم نے بھی اسی کے پاس جانا ہے وہاں اور گلاس مل جائیں گے.غرض ہر نقصان کے وقت اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ کہنا انسانی فطرت کو زنگ سے صاف کر دیتا ہے.(۵) پھر اگر کوئی مکروہ بات یا مکروہ نظارہ پیش آجائے تو اس موقع کو اسلام نے ذکر کے بغیر نہیں چھوڑا بلکہ ہدایت دی کے جب کوئی مکروہ چیز دیکھو تو لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ کہو.(۶) پھر انسان کے اندر گناہ کی کوئی تحریک پید اہو تو ایسے موقع پر اَسْتَغْفِرُاللّٰہَ کا ذکر رکھ دیا.یعنی میں شیطانی حملوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں.(۷)پھر اَعُوْذُ بِاللّٰہِ ایک ذکر ہے جو ہر ایسے اہم کام کے شروع کرنے پر کیا جاتا ہے جس کے راستہ میں شیطانی روکوں کا امکان ہو.مثلاً قرآن کریم پڑھنا ایک اہم کام ہے اور چونکہ شیطان اس میں روکیں پیدا کرتا ہے اس لئے فرمایا فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰہِ (النحل:۹۹) (۸) اس کے علاوہ انسان سونے لگے تب بھی ذکر موجود ہے.چنانچہ ہدایت ہے کہ آیۃ الکرسی اور تینوں قل پڑھو اور اپنے سینہ پر پھونک لو.(ترمذی ابواب الدعوات باب ماجاء فیمن یقرأ القراٰن عند المنام) (۹) آنکھ کھلے تب ذکر موجود ہے کہ اَلْـحَمْدُ لِلہِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْہِ النُّشُوْرُ.(بخاری کتاب الدعوات باب ما یقول اذا نام) (۱۰) اسی طرح بیماری کے وقت بھی ذکرموجود ہے اور شفا ہو نے پر بھی ذکر الٰہی موجود ہے.(بـخاری کتاب المرضٰی باب دعاء العائد للمریض)
Page 92
(۱۱) پاخانہ جانا بظاہر کتنا گندہ فعل ہے مگر وہاں بھی مناسب حال ذکر موجود ہے یعنی اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُبِکَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.(بخاری کتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء) (۱۲) پھر غسل کرنے لگو تب بھی ذکر موجود ہے.(ترمذی ابواب الطھارۃ باب مایقال بعد الوضوء) (۱۳) میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کو لو تو اس موقعہ پر بھی ہمارے کوثر والے آقاؐ نے کہا کہ جب تم آپس میں ملنے لگو تو خدا تعالیٰ کا پہلے ذکر کرو.یعنی اَللّٰھُمَّ جَنِّبْنِی الشَّیْطٰنَ وَ جَنِّبِ الشَّیْطٰنَ مَا رَزَقْتَنَا پڑھ لیا کرو.(بخاری کتاب الدعوات باب ما یقول الرجل اذا اتی اھلہ ) غر ض انسانی زندگی کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں خواہ وہ جذبات کے اظہار کا ہی ہو جہاں کوئی نہ کوئی ذکر موجود نہ ہو.اسلامی مقررہ عبادت کے علاوہ اسلامی عبادت کے بعض حصے اس کے علاوہ اسلام نے عبادت کے بعض اور حصے بھی بتائے ہیں جو دس قسم کے ہیں.(۱) تفکّر.یہ خدا تعالیٰ کی ہستی تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے.تفکّر کے معنے ہیں ذہنی اور فلسفیانہ الجھنوں پر غور کرنا.(۲) شکر.خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ (ابراہیم:۸)جذبۂ شکر فکر کو مدد دیتا ہے اور قربِ الٰہی کی راہیں انسان پر کھلنے لگ جاتی ہیں.(۳) تذکّر.تذکّر اور تفکّر میں فرق ہے.تفکّر کسی ذہنی مسئلہ پر غور کرنے کوکہتے ہیں اور تذکّر کسی پچھلے واقعہ کو یاد کر کے نتیجہ نکالنے کو کہتے ہیں جس کو عبرت بھی کہتے ہیں یہ بھی دل کی صفائی کا ایک بھاری ذریعہ ہے.(۴) شعور.انسان کی فطرت میں جو جذبات ہیں ان پر غو ر کر کے انہیں باہر نکالنا شعور کہلاتا ہے فطرت میں بہت سے احساسات اور جذبات پائے جاتے ہیں اگر ہم ان کو ابھاریں تو وہ بڑی ترقی کا موجب ہو سکتے ہیں.(۵)علم.یہ جگ بیتی کا نام ہے تذکّر آپ بیتی کو کہتے ہیںاور علم جگ بیتی کو.کہانیوں میں بھی آتا ہے کہ آپ بیتی کہوں یا جگ بیتی.اگر یہ علم ہو جائے کہ فلاں آدمی نے یہ یہ اعمال کئے تھے جن سے خرابیاں پیدا ہوئیں تو بہت کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.(۶)فقہ.فقہ کا جذبہ بھی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے قرآن کریم میں آتا ہے لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ(التوبۃ:۱۲۲) فقہ ہر اس مسئلہ علمیہ کو کہتے ہیں جو ظاہر پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ ہم اس کے باطنی اثرات کو سوچیں فکر مسئلہ فلسفیہ کے لئے آتا ہے اور تفقّہ مسئلہ علمیہ کے لئے آتا ہے.(۷) عقل.اس سے بھی اگر کام لیا جائے تو انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو تا ہے جو اسے برے اور بھلے
Page 93
کی تمیز کروا دیتا ہے اور برائیوں سےروک دیتا ہے.جیسے موٹر کی بریک ہو تی ہے عقل بھی انسانی دماغ کی بریک ہے.(۸)ابصار.قرآن کریم میں آتا ہے اَفَلَاتُبْصِرُوْنَ (القصص:۷۳) اس کے معنے ہیں روحانی آنکھ سے دیکھنا اس سے بھی بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں.جن سے انسان کی اصلاح ہو تی ہے.(۹،۱۰)رویت و نظر.یہ دونوں قریب قریب معنوں والے الفاظ ہیں.لیکن ان میں فرق بھی ہے.جہاں تک ظاہر معنوں کا سوال ہے یہ آپس میں مشترک ہیں اور دیکھنے کےمعنوں میں استعمال ہوتے ہیں.لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ رویت اس دیکھنے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ شعور قلبی شامل ہو اور نظر اس دیکھنے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ قوت فکریہ شامل ہو.غرض تفکّر، شکر، تذکّر، شعور، علم، فقہ، عقل، ابصار، رویت اور نظر، یہ دس اسلامی عبادت کے حصے ہیں.جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الگ الگ موقعوں پر بیان کیا ہے.دنیا کا اور کوئی مذہب نہیں جس میں اس عبادت کا ایک حصہ بھی بیان ہوا ہو.زکوٰۃ اور اس کی حکمت زکوٰۃ.نماز فرض و نفل اور معیّن اور غیر معیّن کے بعد اب ہم زکوٰۃ کو لیتے ہیں.اس مسئلہ کو بھی قرآن کریم نے جس تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے اس کی مثال کسی اور کتا ب میں نہیں ملتی.یوں تو بائبل میں بھی لکھا ہے کہ دسواں حصہ زکوٰۃ دی جائے(استثناءباب ۱۴ آیت ۲۱،۲۲) اور ہندو ؤں میں بھی صدقہ و خیرات کی تعلیم ہے(ستیارتھ پرکاش سملاس گیارھواں سوال ۸۳) لیکن ان میں وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئیں جو اسلام نے پیش کی ہیں.(۱) اسلام سب سے پہلے یہ اصل بیان فرماتا ہے کہ تمام ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے.وہ یہ تعلیم پیش کرتا ہے کہ لِلّٰہِ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ( المائدۃ:۱۲۱) آسمانوں اور زمین کی حقیقی مالکیت اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہےکسی انسان کو حاصل نہیں.(۲)دوسرا اصل اسلام یہ پیش کرتا ہے کہ تمام ملکیت اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے لئے پیدا کی ہے.(۳) تیسرا اصل وہ یہ پیش کرتا ہے کہ اس کے سب بندوں کا حق سب ملکیت میں شامل ہے.جیسے شاملات دیہہ ہوتی ہے اور اس میں ہر ایک کا حصہ ہو تا ہے.اسی طرح اس ملکیت میں سب لوگ حصہ دار ہیں.مگر شاملات دیہہ میں تو بعض کا حصہ زیادہ ہو تا ہےاور بعض کا کم.خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے سب کا حق سب ملکیت میں مساوی قرار دیا ہے.ان تین اصول کے نتیجہ میں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ جب تمام بنی نوع انسان کا تمام ملکیت میں حق ہے تو وہ
Page 94
اپنے حقوق کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں مثلا ً امریکہ میں ایک پہاڑی ہے جس میں ہمارا حصہ ہے لیکن ہم ہندوستا ن میں رہتے ہیں ہم اپنا حصہ نہیں لے سکتے امریکہ والوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے.اس صورت میں ہم کیا کریں.اسلام اس مشکل کو حل کرنے کے لئے (۴) چوتھااصل یہ پیش کرتا ہے کہ چونکہ قبضہ اور عمل بھی ایک حق رکھتا ہے اس لئے قابض اور عامل کو کچھ زائد حق ملے گا.مثلاً امریکہ والوں نے اگر اس پہاڑی پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ کچھ شرائط کے ساتھ اس قبضہ کو قائم رکھ سکتے ہیں اور وہ شرائط یہ ہیں.اوّل.جو قبضہ کرنے والے ہیں وہ تسلیم کریں کہ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے.دوم.جب ان کے پاس اپنے اَقلّ حق سے زیادہ ہو تو وہ باقی حقداروں کے لئے ایک کیپیٹل لیوی ادا کریں.جس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی آمد میں سے چالیسواں حصہ دوسروں کے لئے نکال دیا کریں اور یہ بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے یہ حکم ہے اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ دینے کا تو سوال نہیں صرف چالیس سال کے قبضہ میں ہر سال چالیسواں حصہ دے کر وہ چیز اصل حقداروں کی طرف لوٹ آئے گی.اور بعد کی آمد زائد آمد ہو گی.یہی وہ چیز ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے.(۵)پانچواں اصل اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ کوئی شخص مال کو روپیہ کی صورت میںجمع نہ کرے بلکہ اسے چکرمیں رکھےتاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں.(۶) چھٹا اصل اسلام نے یہ مقرر کیا کہ باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی کے امراء غرباء کی خبر گیری کے ذمہ وار ہیں.اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی غریب باقی رہ جائے گا تو اس کی ذمہ واری تم پر ہو گی اور اس کے متعلق خدا تعالیٰ تم سے قیامت کے دن سوال کرے گا.احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کہ میں تم پر بہت خوش ہوں.اس لئے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری کی.بندے استغفار کریں گے اور کہیں گے یا اللہ بھلا تو کہاں اور ہم کہاں.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تو بھوکا، پیاسا، ننگا اور بیمار ہو.اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو! جب تمہارے پاس میرا ایک غریب بندہ آیا اور تم نے اسےکھانا کھلایا تو گویا میں ہی بھوکا تھا جسے تم نے کھانا کھلایا اور جب تمہارے پاس میرا ایک غریب بندہ آیا اور وہ ننگا تھا اور تم نے اسے کپڑے پہنائے تو گویا میں ہی ننگا تھا جسے تم نے کپڑے پہنائےاور جب میرا کوئی بندہ تمہارے پاس آیا اور وہ پیاسا تھا اور تم نے اسے پانی پلایا تو گویا میں ہی
Page 95
پیاساتھا جسے تم نے پینے کو دیا اور جب میرا کوئی بندہ بیمار ہوا اور تم اس کی عیادت کے لئے گئے تو گویا وہ بیمار میں ہی تھا جس کی تم نے عیادت کی.پھر اللہ تعالیٰ بعض اور بندوں سے مخاطب ہوگا اور ان سے کہے گا کہ دیکھو میں بھوکا تھا مگر تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا مگرتم نے مجھے پانی نہ دیا، میں ننگا تھا مگر تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں بیمار تھا مگر تم نے میری عیادت نہ کی.اس پر وہ کہیں گے کہ خدایا ایسا کب ہوا.تو تو بڑی شان والا ہے.اور تو بھوک اور پیاس اور بیماری اور ننگے ہو نے سے پاک ہے.اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تمہارے پاس میرے غریب بھوکے، پیاسے، ننگے اور بیمار بندے آئے اور تم نے ان کی خبر گیری نہ کی تو گویا میری ہی خبر گیری نہ کی.اس لئے جاؤ اور اب اس کی سزا برداشت کرو(مسلم کتاب البر والصلۃ باب فضل عیادۃ المریض).پس صرف زکوٰۃ کا ہی سوال نہیں.اگر زکوٰۃ دینے کے بعد بھی کوئی غریب نظر آتا ہے.تو اسلام اس کی خبر کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیتا ہے.(۷) پھر اسلام نے مختلف غلطیوں کا کفارہ غرباء کی مدد کی صورت میں مقرر کیا ہے.بعض مقامات پر غلاموں کی آزادی ضروری قرار دی ہے اور بعض جگہ انہیں کھانا اور لباس وغیرہ دینا کفارۂ گناہ کے طور پر لازمی قرار دیا ہے.(۸) اس کے علاوہ اسلام نے ہر عبادت ِ نو پر غرباء کا حق مقرر کیا ہے.مثلاً فرمایا.تمہیں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو غریبوں کوکھانا بھی کھلاؤ.عید آرہی ہے تو غرباء کے لئے بھی صدقہ دو(بخاری کتاب الزکٰوۃ باب الصدقۃ قبل العید).حج کے لئے چلے ہو توغرباء کا بھی خیال رکھو.(۹) فتوحات حاصل ہوں تو اس وقت بھی اسلام نے غرباء کے حقوق کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اموال میں ان کو بھی حصہ دار قرار دیا ہے.(۱۰) پھر بچہ کی پیدائش ہو تو حکم دیا کہ عقیقہ کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ.(ابن ماجۃ کتاب الذبائـح باب العقیقۃ) (۱۱) شادی پر حکم دیتا ہے کہ ولیمہ کرو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ.(بخاری کتاب النکاح باب الولیمۃ) (۱۲) کسی کی وفات ہو جائے تو حکم دیا کہ تقسیم ورثہ کے علاوہ میّت کے مال میں سے کچھ یتیموں کو بھی دو.(۱۳) ہر نئی فصل یا نئے پھل کے پیدا ہو نے پر غرباء کا حق مقرر کیا اور حکم دیا کہ وَاٰتُوْا حَقَّہٗ یَوْمَ حَصَادِہٖ (الانعام:۱۴۲) آم، انگور، گیہوں، ماش اور کپاس غرض جو بھی چیز اپنے گھر لاؤ اس میں سے پہلے غرباء کا حق نکالو اور پھر اپنے استعمال میں لاؤ.غرض ہر اہم موقع پر اسلام نے غرباء کے حقوق کو مدّ ِنظر رکھا ہے اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی مثال اور کسی مذہب میں نہیں ملتی.دنیا کا کوئی مذہب نہیں جس نے اس عبادت کو اس طرح پیش کیا ہو.بلکہ ان کی تعلیموں میں
Page 96
اسلام کی تعلیم کا سواں حصہ بھی موجود نہیں.دوسرے مذاہب کے روزوں کے مقابلہ میں اسلامی روزے روزے.پھر روزہ ہے.اجتماعی روزہ کسی اور قوم میں نہیں.چندروزے عیسائیوں میں ہیں اور وہ بھی نامکمل شکل میں.ہندوؤں میں بھی ایسے ہی روزے ہیں.پنڈت کہے گا چولھے کی پکی نہیں کھانی اور ادھر چھ سیر کچا دودھ پی جائے گااور پھر کہے گا میرا روزہ ہے.لیکن اسلام میں ایک مہینہ متواتر اور لگا تارروزے ہیں اور پھر ساتھ ہی یہ ہدایت ہے کہ صرف روزے ہی نہ رکھو بلکہ رمضان کے مہینہ میں خوب عبادتیں کرو اور دعاؤں پر زور دو.بالخصوص رمضان کے آخری ہفتہ میں جس میں لیلۃ القدر ہو تی ہے پس روزہ میں بھی اسلام دوسرے مذاہب پر فضیلت رکھتا ہے.حج اور اس کی حکمت حج.اسلام کا ایک رکن حج ہے جو اجتماعِ قومی کا زبردست ذریعہ ہے.دنیا کے کسی مذہب میں حج فرض نہیں.لیکن اسلام نے سال میں ایک دفعہ تمام صاحبِ استطاعت لوگوں کو ایک مرکز میں اکٹھا ہو نے کا حکم دیا ہے.اس سے کئی قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں.جب امیر اور غریب،حاکم اور محکوم، عالم اور جاہل سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو وہ قومی ضروریات پر غور کریں گے.اپنی کمزوریوں پر نگاہ دوڑائیں گے اوران کو دور کرنے کی کوشش کریں گے.اسی طرح حج کے ذریعہ اسلام نے مرکز کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دلائی ہے.جس سے آگے قوم کی درستی ہوتی ہے اور وہ ترقی کی طرف اپنا قدم بڑھا سکتی ہے غرض عبادت کو لے لو یا زکوٰۃ کو لے لو یا روزہ کو لے لو یا حج کو لے لو سب میں اسلام نے بنی نوع انسان کو جو تعلیم دی ہے اس کا عشرِ عشیر بھی کسی دوسرے مذہب میں نہیں پایا جاتا.تفصیل شرائع اور اس کی وجہ سے اسلامی تعلیم کی فضیلت اصولِ شرائع میں قرآن کریم کی فضیلت ثابت کرنے کے بعد اب میں تفصیلِ شرائع کو لیتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اصولی امور میں ہی قرآن کریم کو کتب سابقہ پر فوقیت حاصل نہیں بلکہ تفصیلِ شرائع میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا ہوا ہے اور کوئی دوسری کتاب اس پہلو کے لحاظ سے بھی قرآن کریم کامقابلہ نہیں کر سکتی.اسلام میں عورتوں کے حقوق تفصیل شرائع میں جو چیز سب سے پہلے آتی ہے وہ عورتوں کے حقوق کا مسئلہ ہے.قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے آپ کے جوڑے کا بھی ذکر کیا ہے جس سے آگے سلسلۂ مخلوقات چلا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی تمام کتابوں کو پڑھ جاؤاُن میں عورتوں کے حقوق کا پتہ ہی نہیں چلے گا اور نہ کسی کتاب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عورت بھی انسانیت کا ایک جزو ہے.قرآن کریم وہ پہلی کتاب ہے جس نے عورت کے حقوق کو تسلیم کیا ہے اور صرف تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ اس پر
Page 97
اتنا زور دیا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ نئے علوم کا ایک دروازہ کھل گیا ہے.مثلاً نکاح کے موقعہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتین آیات منتخب فرمائیں(ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ انتخاب الہامی تھا)ان میںعورت کے حقوق پر بڑازور دیا گیا ہے اور اس کی اہمیت پوری طرح واضح کی گئی ہے.چنانچہ پہلی آیت کو ہی لے لو.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً١ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا (النسآء:۲) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اس نے سب انسانوں کو نفسِ واحدہ سے پیدا کیا ہے یعنی مرد اور عورت دونوں ایک جنس سے ہیں.دونوں ایک ہی قسم کا دماغ لے کر آئے ہیں.ایک ہی قسم کے احساسات لے کر آئے ہیں اور ایک ہی قسم کے جذبات لے کر آئے ہیں.دیکھو پہلے فقرہ میں ہی عورت کے حقوق پر کتنا زور دیا گیا ہے اور کس طرح بنی نوع انسان کو اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ عورت میں دماغ نہیںاور تم جس طرح چاہو اس پر حکومت کر سکتے ہویا جس طرح چاہو اس سے سلوک کر سکتے ہو.عورت بھی تمہاری طرح جذبات اور احساسات رکھتی ہے اور وہ بھی تمہاری طرح دماغ رکھتی ہے.اس لئے اسے اپنے جیسا سمجھو.ادنیٰ اور ذلیل قرار نہ دو.اس اصولی تعلیم کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ انہیں اہم امور میں عورتوں سے مشورہ لینا چاہیے اور آپ خود بھی عورتوں سے مشورہ لیا کرتے تھے اور اس بارہ میں انہیں اس قدر آزادی حاصل تھی کہ احادیث میں آتا ہے آپ نے ایک دفعہ گھر سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا.صحابہؓ میں یہ چرچا ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے.حضرت عمر ؓ کی ایک بیٹی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تھیں.انہیں ایک دوست نے یہ اطلاع دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے.حضرت عمرؓ یہ سنتے ہی پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے.دیکھا تو وہ رو رہی تھیں.آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آپ گھر سے چلے گئے ہیں.پھر حضرت عمر ؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا.یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہم تو عورتوں کو ڈنڈے سے سیدھا کیا کرتے تھے.پھر آپ نے ایسی تعلیم دینی شروع کر دی کہ عورتیں ہمارے سر چڑھنے لگیں.میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ تو اس معاملہ میں نہیں بول سکتی.تو میری بیوی نے کہا چل چل وہ دن گئے جب ہمارا کوئی حق نہیں تھا.اب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں.تم کون ہو جو مجھے روکو.میں سمجھتا تھا کہ اس کا نتیجہ کسی دن برا ہی نکلے گا.چنانچہ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آپ کو اپنی بیویوں کو طلاق
Page 98
دینی پڑی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور آپؐنے فرمایا.عمرؓ میں نے اپنی بیویوں کو طلا ق نہیں دی.صرف مصلحتاً کچھ وقت کے لئے ان سے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے(بخاری کتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشـرفة....).گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ عورتوں میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مردوں سے کم نہیں.حضرت عمر ؓ کے زمانہ کے واقعات سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر کوئی حکم دیتے تو بعض دفعہ عورتیں صاف صاف کہہ دیتیں کہ یہ حکم آپ کس طرح دے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے(تفسیر قرطبی زیر آیت النسآء :۲۰،۲۳).قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح کہتی تھیں یا غلط اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اسلام نے عورت کو اجتماعی معاملات میں رائے دینے کا حق دیا ہے اور اس پر اتنا زور دیا ہے کہ اس کی مثال دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی.پھر فرمایا.عورت کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں ہو سکتی(ابو داؤد کتاب النکاح باب في البكر يزوجها ابوها ولا يستأمرها).اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ والدین جہاں چاہتے عورت کی شادی کر دیتے.اس کی مرضی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا اور عورت کو ان کی بات ماننی پڑتی تھی.مسلمانوں نے بھی اس زمانہ میں اگرچہ یہ حق تلف کر دیا ہے مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ اسلامی تعلیم ناقص ہے.اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اگر کوئی شادی ہو تو وہ باطل ہے.کتنا بڑا حق ہے جو قرآن کریم نے عورتوں کو دیا ہے.پھر قرآن کریم میں دیکھ لو.بچے کا دودھ چھڑا نا بھی عورت کی مرضی پر رکھا ہے اور اسے ایسی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس کی مثال اور کسی کتاب میں نہیں ملتی.پھر عورت کو الگ گھر کا حق دیا ہے.اس کا مہر مقرر کیا ہے اور کہا ہے کہ عورت اپنی جائیداد کی آپ وارث ہے.یورپ میں اب قریباً پچاس سال سے عورتوں کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے.ورنہ اس سے پہلے عورت کی جائیداد اس کی اپنی جائیداد نہیں سمجھی جاتی تھی.بلکہ بعض لوگ نواب اور رئیس بن کر اور اپنے آپ کو مالدار ظاہر کر کے دھوکہ سے ان سے شادی کر لیتے تھے اور عورت کچھ نہیں کر سکتی تھی.خاوند کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ اس کی جائیداد کو بیچے یا رکھے.لیکن اسلام نے عورت کی جائیداد کو اس کی ذاتی ملکیت قرار دیا ہے اور اس پر اتنا زور دیا ہے کہ صحابہؓ کو شبہ پڑ گیا کہ مرد کے لئے یہ بھی جائز نہیں کہ عورت کی جائیداد میں سے کچھ اس کی مرضی سے ہی لے لے.چنانچہ اس کے لئے اسلام نے علیحدہ حکم دیا اور بتایا کہ تم عورت کا خوشی سے دیا ہوا تحفہ استعمال کر سکتے ہو.غرض اسلام نے عورت کے حقوق کی جس طرح حفاظت کی ہے ویسی حفاظت اور کسی مذہب نے نہیں کی.پھر سب سے مقدم ماں باپ ہیں.ماں باپ کے ذریعہ سے نسل چلتی ہے.انسان میں جو قابلیت پیدا ہوتی
Page 99
ہے وہ ماں باپ کے ذریعہ سے ہی پیدا ہوتی ہے.اگر ماں باپ اپنی اولاد کو نہ پڑھائیں تو وہ کس طرح دنیا میں عزت حاصل کر سکتی ہے.ماں باپ اگر اپنے بچوں کی پرورش نہ کریں تو وہ کس طرح بڑے ہو سکتے ہیں.مگر اس کے باوجود یہ عجیب بات ہے کہ کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے اولاد کے مال میں ماں باپ کا حق تسلیم کیا ہو.تورات میں بے شک ایسے احکام پائے جاتے ہیں کہ ماں باپ کا ادب کرو.مگر اولاد کے مال میں ان کا حق نہیں رکھا.یہ قرآن کریم ہی ہے جس نے ان کا حق رکھا ہے اور بڑا اہم حق رکھا ہے.قرآن کریم نے والدین کو اولاد کے ورثہ کا حقدار تسلیم کیا ہے.بلکہ بعض صورتوں میں جب اولاد زیادہ ہو تو ماں باپ کواولاد سے زیادہ حق ملتا ہے.یعنی اگر مرنے والے کی اولادزیادہ ہو تو اولادکا حق کم ہو جائے گا اور ماں باپ کا حق زیادہ ہو جائے گا.یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی.کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے ماں باپ کے ایسے حقوق مقرر کئے ہوں.یہ تو سب کہتے ہیں کہ ماں باپ کا لحاظ کرو، ادب کرو، عزت کرو.مگر تمام باتیں صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہوتی ہیں.اسلام ہی ہے جس نے اولاد کے مال میں والدین کا حق قائم کر کے ان کے مرتبہ کو تسلیم کیا ہے.پھر لڑکی کو وراثت کا حق نہیں تھا.اسلام نے اس کے حق کو بھی قائم کیا اور فرمایا کہ لڑکی بھی جائیداد کی ویسی ہی وارث ہو سکتی ہے جیسے لڑکا.اور وہ اس جائیداد پر پورا حق رکھتی ہے.درحقیقت اسلام بنی نوع انسان کو اس نکتہ کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جس طرح دنیا کی دولت مشترک ہے.کسی ایک کی حقیقی ملکیت نہیں اس طرح تمہاری کمائی میں بھی ہر ایک کا حق ہے.کیونکہ کوئی اکیلا نہیں کما سکتا.بلکہ اسے دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے.اس لئے وہ جب بھی کمائے گا اس میں دوسروں کا حق ہو گا.اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ بڑی بڑی تجارتیں شہروں میں ہی ہوتی ہیں.گاؤں میں نہیں ہوتیں.شہروں میں کیوں زیادہ ہوتی ہیں.اس لئے کہ شہروں میں نقل و حرکت کے سامان موجود ہوتے ہیں، پکی سڑکیں ہوتی ہیں، ریل ہوتی ہے، لاریاں ہوتی ہیں اور دوسرے ذرائع نقل و حمل موجود ہوتے ہیں.شہروں میں کیوں ہوٹل کھولے جاتے ہیں اس لئے کہ وہاں بہت لوگ ہوتے ہیں.گاؤں میں اگر ہوٹل کھولا جائے تو وہ نہیں چل سکتا.پھر شہروں میں سرائیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں اور ان میں ٹھہرتے ہیں گاؤں میں سرائے نہیں ہوتی.پھر گاؤں میں بڑے بڑے سٹور نہیں ہوتے کہ جہاں کوئی مال رکھ سکے.یہ ساری چیزیں فردی طور پر نہیں بلکہ مجموعۂ آبادی کی وجہ سے لوگوں کو میسر آتی ہیں.اس لئے جو کچھ شہری کماتا ہے اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے اس لئے اسلام نے یہ قانون بنا دیا کہ جو کوئی کمائی کرتا ہے اس میں اس کے ہمسائیوں کا بھی حق ہے کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ کما نہ سکتا.پھر فرمایا یہ حق ہمسائیوں کو مفت نہیں دیا جارہا.بلکہ اس لئے
Page 100
دیا گیا ہے کہ ان کا وجود تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے.اگر شہر نہ ہوتا تو کمائی بھی نہ ہوتی.پس دوسرے لوگ چونکہ کمائی کاموجب ہیں اس لئے ان کا بھی اس کمائی میں حصہ ہے.اسی طرح کوئی خاندان اکیلا کمائی نہیں کر سکتا.جب تک اس کے ساتھ باقی افراد خاندان بھی شریک نہ ہوں.مثلاً دیکھ لو کوئی شخص تجارت کے لئے باہر کیسے جا سکتا ہے جب تک اس کی بیوی نہ ہو.اس کی بیوی گھر کا انتظام کرتی ہے تب وہ کماتا ہے.پھر اس کے بچے ہیں وہ اس کا کچھ نہ کچھ بوجھ اٹھاتے ہیں.چھوٹی موٹی تجارت میں بھی حصہ لے لیتے ہیں.ایک بسا بسایا گھر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مال محفوظ رہتا ہے.اسی لئے اس کے مال میں ان سب کا حق ہوتا ہے.پھر بھائی ہے وہ کام تو نہیں کرتا مگر جب وہ کسی کو قرض دیتا ہے اس کی وصولی میں اس کے بھائیوں کا بھی دخل ہوتا ہے.اعلیٰ اخلاق والا اور شریف انسان تو خود بخود قرض واپس کر دیتا ہے لیکن ادنیٰ اخلاق والا آدمی اس لئے قرض واپس کرتا ہے کہ اگر اس نے قرض واپس نہ کیا تو اس کی قوم اور اس کے بھائی بند میرے ساتھ لڑیں گے گویا قوم اور جتھے نے اس کا مال واپس دلوایا.اگر اس مقروض پر قوم اور جتھہ بازی کا رعب نہ ہوتا تو وہ کبھی مال واپس نہ کرتا.یہی حکمت ہے جس کی بنا پر قرآن کریم نے تمام رشتہ داروں کا جن کا قریبی تعلق ہوتا ہے ورثہ میں حصہ مقرر کر دیا ہے.مثلاً ماں، باپ، بیوی، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن وغیرہ.پھر ان کے فقدان کی صورت میں دور کے رشتہ دار وارث ہو جاتے ہیں.جیسے دادا، دادی، نانا، نانی، پوتا، پوتی، بھتیجے وغیرہ.اور یہ نکتہ کہ ہر ایک کی کمائی میں عائلی حق ہوتا ہے قرآن کریم نے ہی بیان کیا ہے.اور کسی کتاب نے بیان نہیںکیا.پھر اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا.جیسے فرمایا جس کی دو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو خدا تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ ؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک غریب عورت میرے پاس آئی.اس کی دو لڑکیاں تھیں ایک لڑکی کو اس نے اپنی دائیں طرف بٹھایا اور دوسری لڑکی کو اس نے اپنی بائیں طرف بٹھایا اور کہا مجھے کچھ کھانے کے لئے دو.ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہ تھی.میںنے تلاش کیا تو ایک کھجور نکل آئی.میں وہ کھجور لے کر اس کے پاس آئی اور کہا اس وقت ہمارے گھرمیں یہی ایک کھجور ہے یہ لے لو.اس عورت نے وہ کھجور اپنے منہ میں ڈالی اور اندازہ سے اس کے دو برابر حصے کئے اور پھر نصف کھجور ایک لڑکی کو دے دی اور نصف کھجور دوسری کو دی خود بھوکی رہی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر سنا تو فرمایا.اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو تعلیم دلوائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے(ابن ماجہ کتاب الادب باب بر الوالد والاحسان).دیکھو
Page 101
اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر کتنا زور دیا ہے.لڑکوں کو تو لوگ اس لئے تعلیم دلواتے ہیں کہ یہ بڑ ے ہو کر نوکریاں کریں گے مگر عورتوں کے فرائض خدا تعالیٰ نے نوکریوں والے مقرر نہیں کئے.اگرچہ آج کل مسلمان لڑکیاں بھی نوکری کر لیتی ہیں مگر اسلام نے عورت پر گھر کی ذمہ واریاں رکھی ہیں اس لئے اس کی تعلیم کمائی میں ممد نہیں ہوسکتی.مگر اس کے باوجود اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر زور دیا اور یہ چیز دوسری کتابوں میں نہیں پائی جاتی.پھر بیوی کے حقوق ہیں.اسلام نے ان کی بھی تفصیلات بیان کی ہیں اور ہدایت دی ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت اورپیار کا سلوک ہونا چاہیے.بیوی سے محبت تو سب کرتے ہیں بلکہ بعض لوگ اپنی بیویوں پر عاشق ہو کر مذہب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں.مگر سوال یہ ہے کہ ان کے مذہب نے ان کا کیا حق رکھا ہے.محبت تو ایک فطرتی چیز ہے اور فطرت گمراہی کی طرف بھی لے جاتی ہے اور ہدایت کی طرف بھی لے جاتی ہے.اصل سوال مذہب کا ہے مگر دوسرے مذاہب نے بیوی کے کوئی حقوق مقرر نہیں کئے.یہ حقوق صرف اسلام نے ہی مقرر کئے ہیں.اسلام نے ہی یہ حکم دیا ہے کہ بیوی کو مارو پیٹو نہیں بلکہ اس کی دل جوئی کرو.پھر فرمایا.اس کے کھانے پینے کی ذمہ واری تم پر ہے(ابو داؤد کتاب النکاح باب فی حق المرأۃ علی زوجھا).اب تک یوروپ میں عام طورپر یہی دستور رہا ہے کہ بیوی کا مال خاوند کا ہوتا ہے اور وہ جس طرح چاہے اسے خرچ کر سکتا ہے.خواہ وہ اسے لٹا دے یا رکھ لے.عورت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا.مگر اسلا م نے اسے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد کی آپ مالک ہے وہ جس طرح چاہے اسے خرچ کرے اور جس کو چاہے دے وہ خود اس کی ذمہ وار ہے.لیکن مرد اس کا کفیل ہے.عورت کے پاس اگر لاکھ روپیہ ہو اور مرد کے پاس پانچ روپے ہوں تو مرد اسے پانچ روپوں میں سے ہی کھلائے گا.کیونکہ اس نے اس سے شادی کی ہے اور اسے اپنی بیوی بنایا ہے.وہ اس کی روٹی اور کپڑے کا آپ ذمہ وار ہے.اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ عورت سے اس کی رقم میں سے کچھ جبراً لے لے.پھر طلا ق کا مسئلہ لے لو.اسلام نے اس پر کئی قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں تاکہ عورت کی حق تلفی نہ ہو.سزا کے متعلق ہدایت دی کہ اس میں احتیاط سے کام لو اور ایسی سزا نہ دو جس کا بدن پر نشان پڑ جائے غر ض اسلام نے جس تفصیل کے ساتھ ان حقوق کو بیان کیا ہے اس کی مثال کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی.رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی سے بہتر ہے.(ابن ماجہ کتاب النکاح باب حسن معاشـرۃ النساء) پھر اولاد کے متعلق احکام دیئے ہیں.پہلے یہ سمجھاجاتا تھا کہ اولاد باپ کا حق ہے کیونکہ وہ اس کے نطفہ سے پیدا
Page 102
پھر اولاد کے متعلق احکام دیئے ہیں.پہلے یہ سمجھاجاتا تھا کہ اولاد باپ کا حق ہے کیونکہ وہ اس کے نطفہ سے پیدا ہوئی ہے اور یہ جائز سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی چاہے تو اپنی اولاد کو بیچ ڈالے چاہے تو اسے مار ڈالے.چنانچہ لڑکیوں کو مارنے کا بعض قبائل عرب میں رواج تھا(معالم التنزیل زیر آیت وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ).اسی طرح اولاد کو فروخت کر دینے کا بھی رواج تھا.اسلام نے اس پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اگر کوئی آزاد کو بیچے تو وہ واجب القتل ہے.اور لڑکیوں کے متعلق سختی سے فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم لڑکی کو مار دو گے تو پھر چھوڑدیئے جاؤ گے.بلکہ قیامت کے دن تم سے اس کے متعلق سوال کیاجائے گا اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ تمہاری لڑکی تھی اور تمہارے نطفہ سے پیدا ہوئی تھی.وہ تمہاری لڑکی بعد میں بنی تھی پہلے ہماری بندی تھی.تمہیں کیا حق تھا کہ تم اسے مار ڈالتے.فرمایا وَ اِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُىِٕلَتْ(التکویر:۹) تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم ان کو مارڈالو.ہم نے اسے نسل انسانی کوجاری رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے.اگر تم لڑکیوں کو مار ڈالو گے تو قیامت کے دن تم اس کے متعلق سوال کئے جاؤ گے.غرض وہ حقوق جو اسلام نے عورت کو دیئے ہیں وہ پہلی کتابوں میں کہیں نظر نہیں آتے.شہریت کے حقوق پھر شہریت کے حقوق ہیں.جب انسان خاندان سے نکلتا ہے تو شہریت کی طرف آتا ہے.شہریت میں سب سے مقدّم اور سب سے پہلے ہمسائے ہیں.دیگر مذاہب میں بھی ہمسایوں کے متعلق تعلیم آتی ہے مگر جس رنگ میں اسلام نے ہمسایہ کے حقوق کو بیان کیا ہے اس رنگ میں اور کسی مذہب نے بیان نہیں کیا.اسلام نے اس مسئلہ پر اتنا زور دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آیا اور اس نے ہمسائے کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ میں نے سمجھا وہ اسے وارث قرار دے دےگا(بخاری کتاب الادب باب الوصاۃ والجار).پھر اسلام نے ہمسائے کے حقوق کے متعلق تفصیلی احکام دیئے ہیں اور ان کا خیال رکھنے کی اس قدر تاکید کی ہے کہ حضرت عباس ؓ کے متعلق آتا ہے کہ آپ جب گھر آتے تو پوچھتے کہ کیا ہمارے یہودی ہمسائے کو بھی کچھ دیا ہے؟ آپ کے ہمسایہ میں ایک یہودی رہتا تھا آپ اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس کو نظر انداز کرنا گناہ سمجھتے تھے.پھر شہریت کے حقوق کے ماتحت شہروں کی غذا اور ہوا اور پانی کا مسئلہ آتا ہے.اگر یہ تینوں چیزیں اچھی نہیں ہوں گی تو لازماً لوگوں کی صحت خراب ہو جائے گی.اس لئے اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کھڑے پانی میں پیشا ب نہ کرو.کھڑے پانی میں گندی چیزیں نہ ڈالو(بخاری کتاب الوضوء باب البول فی الماء الدائم).یہ صاف بات ہے کہ جب پانی گندہ نہیں ہوگا تو پانی کی کمی والے علاقوں میں لوگوں کی صحتیں نہیں بگڑیں گی.آج کل تو لوگ حفظان صحت کے اصول سے بہت حد تک واقف ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے اس وقت دیا جب لوگوں کو ان اصول کا کچھ بھی علم نہیں تھا.دیکھو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب پر حاصل ہے.
Page 103
کتنی بڑی فضیلت ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب پر حاصل ہے.پھر تنگ اور گنجان آبادی میں رہنے سے صحت گر جاتی ہے.اس کے متعلق بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گلیاں اور سڑکیں کھلی ہونی چاہئیں تاکہ گندی ہوا سے لوگوں کی صحت پر برا اثر نہ پڑے.آپ نے اس زمانہ میں جب اونٹوں اور گھوڑوں کا رواج تھا سڑکوں کے متعلق جو اصول مقرر فرمائے ان کے مطابق چھوٹی گلی کم سے کم آٹھ فٹ سے دس فٹ کی بنتی ہے اور بڑی گلی کم سے کم پندر ہ سے بیس فٹ کی.جب اونٹ اور گھوڑے کے لئے اتنی بڑی سڑک کی ضرورت تھی تو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ لاریوں اور موٹروں کے لئے اس سے تین گنا سڑک ہونی چاہیے.اس صورت میں چھوٹی گلیاں کم سے کم ۲۱ سے ۳۰ فٹ کی بن جائیں گی اور بڑی گلیاں کم سے کم ۴۵سے ۶۰فٹ کی.پھر فرمایا جہاں لوگ اکٹھے ہوں وہاں گند نہیں پھینکنا چاہیے.آپؐ نے فرمایا اگر مسجد میں کوئی شخص تھوک دے تو اس کا فرض ہے کہ وہ اسے وہاں سے اٹھائے اور دوسری جگہ جا کر دفن کرے(بخاری کتاب الصلٰوۃ باب کفارۃ البزاق فی المسجد).اس سے ایک عام قانون نکل آیا کہ جہاں بھی اجتما ع ہو وہاں کوئی گندی چیز نہیں پھینکنی چاہیے.اسلام کی حکیمانہ تعلیم پھر راستوں کے متعلق فرمایا کہ راستوں پر کوئی ضرررساں چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کو اٹھانا نیکی اور ثواب کا کام ہے(بخاری کتاب المظالم باب اماطۃ الاذی).رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ر استوں سے کانٹے چن چن کر ایک طرف کر دیتے تھے اسی طرح راستوں پر پاخانہ پھرنے کی آپ نے ممانعت فرمائی اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بھڑکانے والا فعل قرار دیا(مسلم کتاب الطھارۃ باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال).یہ وہ زمانہ تھا جسے جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں.مگر آج لاہور، کوئٹہ، راولپنڈی، پشاور اور دوسرے بڑے بڑے شہروں کو دیکھ لو.لوگ گھروں سے گند اٹھا کر دروازوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناجائز ہی قرار نہیں دیا بلکہ اس فعل کو قابلِ مؤاخذہ قرار دیا ہے.غرض پانی کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرو اور نہ اس میں گند پھینکو.گلیاں کشادہ رکھنے کا اصول مقرر فرمایا.نجاست کو پھیلانے سے منع فرمایا.اجتماع کی جگہ پر گند پھینکنے سے منع فرمایا.اجتماع کے مواقع پر جانے سے پہلے یہ ہدایت فرمائی کہ نہاؤ، دھوؤ اور خوشبو لگاؤ تا جسموں اور سانسوں سے جو بدبُو پیدا ہو جاتی ہے وہ خوشبو سے دور ہو جائے(بخاری کتاب الـجمعۃ باب الطيب للجمعة) بلکہ فرمایا کہ یہ پسندیدہ امر ہے کہ اجتماع سے پہلے اس جگہ پر خوشبو جلائی جائے تاکہ ہوا میں خوشبو پھیل جائے اورجرمز فنا ہو جائیں(ترمذی ابواب الـجمعۃ باب ماذکر فی الطییب).اسی طرح لوگوں کی بغلوں اور کپڑوں
Page 104
وغیرہ سے جو بُو آتی ہے وہ نہانے دھونے سے دور ہو جائے گی اور جو باقی رہ جائے گی وہ عطر لگانے سے دور ہو جائے گی.دیکھو یہ کتنی بڑی حکیمانہ تعلیم ہے جو آپ نے دی اور اس وجہ سے دی کہ کہیں لوگوں کی صحتیں خراب نہ ہوجائیں اور وہ بیمار ہو کر دنیا میں ترقی کرنے سے نہ رہ جائیں.پھر شہری حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ لین دین کے معاملات میں خرابی نہ ہو.ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس حق کو بھی نظر انداز نہیں کیا.چنانچہ اسلام نے بھاؤ کو بڑھانے اور مہنگا سودا کرنے سے روکا ہے.اسی طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے اور ان کو تجارت میں فیل کرنے کے لئے بھاؤ کو گرادینے سے بھی منع فرمایا.ایک دفعہ مدینہ میں ایک شخص ایسے ریٹ پر انگور بیچ رہا تھا جس ریٹ پر دوسرے دوکاندار نہیں بیچ سکتے تھے.حضرت عمرؓپاس سے گذرے تو انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا کیونکہ اس طرح باقی دوکانداروں کو نقصان پہنچتا تھا(فقہ حضرت عمرؓ ڈاکٹر محمد رواس قلعہ جی صفحہ ۱۷۱).غرض اسلام نے سودا مہنگا کرنے سے بھی روک دیا اور بھاؤ کو گرادینے سے بھی روک دیا تاکہ نہ دوکانداروں کو نقصان ہو اور نہ پبلک کو نقصان ہو.پھر اسلام نے وبا زدہ شہر سے دوسرے شہر میں جانے سے روک دیا.کیونکہ اس طرح وہاں بھی بیماری پھیل جاتی ہے.آج کل غلطی سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بیماری والے شہر سے نکلنا منع ہے حالانکہ وبا زدہ شہر سے نکلنا منع نہیں بلکہ جائز ہے اور صحابہ ؓ نے خود اس پر عمل کیا ہے.جو چیز منع ہے وہ ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں جانا ہے.جنگلوں میں پھیل جانے سے شریعت میں کہیں منع نہیں کیا گیا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قیصر سے جنگ ہوئی جس میں حضرت ابو عبیدہ فوج کے کمانڈر تھے اس وقت لشکر میں طاعون پھیل گئی اور بہت سے آدمی طاعون سے فوت ہو گئے.آپ نے صحابہ ؓ سے مشورہ کیا اور مقامی لوگوں سے بھی پوچھا مقامی لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسے مواقع پر شہروں سے نکل کر کھلے علاقوں میں چلے جانا چاہیے.چنانچہ اکثر صحابہ نے اس کی تصدیق کی اور پہاڑوں پر چلے گئے لیکن ابو عبیدہ ؓ وہیں رہے اور آخر بیماری سے شہید ہوئے(بخاری کتاب الطب مایذکر فی الطاعون ).صحابہؓ نے اس وقت یہی استدلال کیا کہ اسلام کی تعلیم کے رو سے وبا زدہ علاقوں سے نکل کر دوسرے شہرو ں میں جانا منع ہے تا دوسروں کو بیماری نہ لگ جائے جنگلوں میں جانا منع نہیں.یہ کتنا بڑا قانون ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا.اس وقت متعدی امراض کی ابھی دریافت نہیں ہوئی تھی ان امراض کی دریافت بہت دیر بعد ہوئی ہے مگر آپ نے الٰہی نور اور فیوض قرآنیہ سے حصہ لے کر حکم دے دیا کہ بیماری کے وقت ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھاگ کر نہیں جانا چاہیے تاکہ وہاں بھی بیماری نہ پھیل جائے ہاں میدانوں اور جنگلوں میں اِدھر اُدھر پھیل جانے کی ممانعت نہیں.
Page 105
پھر تعلیم کا انتظام ہے پہلے لوگ فرداً فرداً اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے تھے.قومی طور پر تعلیم دلوانے کا حق صرف اسلام نے ہی تسلیم کیا ہے.بدر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں سے کہا کہ ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے.تم مدینہ کے دس دس لڑکوں کو پڑھا دو اس کے بدلہ میں تمہیں رہا کر دیا جائے گا(مسند احمد بن حنبل مسند عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ).ان قیدیوں نے دس دس لڑکوں کو پڑھایا اور پھر انہوں نے آگے پڑھایا.پھر جو ان سے پڑھے انہوں نے آگے پڑھایا.اس طرح ہر انصاری لکھنا پڑھنا سیکھ گیا.قیدی کا روپیہ قومی روپیہ ہوتا ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے تعلیم دلوا کر یہ ثابت کر دیا کہ قومی روپیہ قومی تعلیم پر خرچ ہو سکتا ہے اور یہ کہ تعلیم دلانے کی ذمہ واری حکومت پر ہے.ملکی حقوق کے متعلق اسلامی تعلیم پھر اسلا م ہی ہے جس نے ملکی حقوق بھی قائم کئے ہیں.اسلام کے نزدیک ہر فرد کی خوراک، رہائش اور لباس کی ذمہ وار حکومت ہے اور اسلام نے ہی سب سے پہلے اس اصول کو جاری کیا ہے.اب دوسری حکومتیں بھی اس کی نقل کر رہی ہیں مگر پورے طور پر نہیںبیمے کئے جا رہے ہیں، فیملی پنشنیں دی جارہی ہیں.مگر یہ کہ جوانی اور بڑھاپے دونوں میں خوراک اور لباس کی ذمہ وار حکومت ہوتی ہے یہ اصول اسلام سے پہلے کسی مذہب نے پیش نہیں کیا.دنیاوی حکومتوں کی مردم شماریاں اس لئے ہوتی ہیں تا ٹیکس لئے جائیں یا فوجی بھرتی کے متعلق یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت کتنے نوجوان مل سکتے ہیں.مگر اسلامی حکومت میں سب سے پہلی مردم شماری جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کروائی گئی تھی.وہ اس لئے کروائی گئی تھی تاکہ تمام لوگوں کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے(تاریخ الطبری سنۃ۲۳ھـ حمله الدرة وتدوينه الدواوين) اس لئے نہیں کہ ٹیکس لگایا جائے یا یہ معلوم کیا جائے کہ ضرورت کے وقت فوج کے لئے کتنے نوجوان مل سکیں گے.بلکہ وہ مردم شماری محض اس لئے تھی کہ تا ہر فرد کو کھانا او رکپڑا مہیا کیا جائے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مردم شماری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ہوئی تھی(بخاری کتاب الجھاد والسیر باب کتابۃ الامام الناس) مگر اس وقت ابھی مسلمانوں کو حکومت حاصل نہیں ہوئی تھی.اس لئے اس مردم شماری کا مقصد محض مسلمانوں کی تعداد معلوم کرنا تھی.جو مردم شماری اسلامی حکومت کے زمانہ میں سب سے پہلے ہوئی وہ حضرت عمر ؓ کے زمانہ میں ہوئی اور اس لئے ہوئی تاکہ ہر فرد کو کھانا اور کپڑا مہیا کیا جائے.یہ کتنی بڑی اہم چیز ہے جس سے تمام دنیا میں امن قائم ہو جاتا ہے.صرف یہ کہہ دینا کہ درخواست دے دو اس پر غور کیا جائے گا اسے ہر انسان کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی.اس لئے اسلام نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ کھانا اور کپڑا حکومت کے ذمہ ہے اور یہ ہر امیر اور غریب کو دیا جائے گا خواہ وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو اور خواہ وہ آگے
Page 106
کسی اور کو ہی کیوں نہ دےدے تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہوکہ اسے ادنیٰ خیال کیا جاتا ہے.تجارت کے متعلق اسلامی تعلیم پھر تجارت ہے.اس کے متعلق بھی اسلام نے کئی قسم کے اصول مقرر کردیئے ہیں تاکہ کوئی تجارت ایسی نہ ہو جس میں دھوکا ہو.اسلام کہتا ہے کہ بغیر دیکھے مال نہیں لینا چاہیے.مثلاً کوئی تھان ہو تو کوئی دوکاندار اسے یوں ہی نہیں بیچ سکتا.بلکہ خریدار اگر اسے دیکھنا چاہے تو دوکاندار کا فرض ہو گا کہ دکھائے.پھر یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی دوکاندار اپنے گاہک سے کہے کہ تم اگر اسے اسی طرح لے لو تو میں تمہیں کم قیمت پر دے دوں گا یا کوئی کنکر مار دے اور کہے کہ جس چیز پر یہ کنکر پڑے وہ میری چیز ہے یا کوئی کہے کہ میں یہ ڈھیر خریدتا ہوں اور اس کا وزن نہ کرے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار گئے وہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈھیر گندم کا اتنے کا ہے اور یہ ڈھیر اتنے کا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا تو نیچے کے دانے گیلے تھے.آپ کو غصہ آگیا اور فرمایا یہ دانے گیلے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے دانے گیلے ہو گئے ہیں.آپ نے فرمایا گیلا حصہ اندر کیوں ڈال دیا گیا ہے.پھر آپ نے اس قسم کے سودے کو ناجائز قرار دے دیا.اسی طرح فرمایا کہ لین دین میں کسی قسم کا دھوکا نہ ہو.(مسلم کتاب الایـمان باب قول النبیّ من غشنا فلیس منا و بخاری کتاب البیوع باب مایکرہ من الخداع فی البیع ) پھر اسلام نے جوئے کو حرام قرار دے دیا کیونکہ اس کے ذریعہ بھی انسان ایسے طور پر کماتا ہے جس سے بہت لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور صحیح تجارت سے رغبت ہٹ جاتی ہے.لاٹریاں بھی اسی میں شامل ہیں.آج کل مسلمان یہ کام کرتے ہیں مگر یہ بھی جوئے میں شامل ہے اور جؤا ناجائز ہے خواہ وہ کسی شکل میں ہو.خواہ قرعہ ڈال کر کھیلا جائے یا نشانہ مار کر کھیلا جائے اسلام نے اسے ناجائز قرار دیا ہے.پھر قرآن کریم نے کہا ہے کہ جب بھی تم سودا کرو اس کی تحریر دو.انگریزی فرمیں میمو دیتی ہیں اور سارا یوروپ فخر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں میمو لئے جاتے ہیں مگر یہ اصول سب سے پہلے قرآن کریم نے پیش کیا تھا.اگر مسلمان اسے چھوڑ بیٹھے ہیں تو یہ ان کی بد قسمتی ہے.پھر سود ہے اسے بھی اسلام نے منع فرمایا ہے.سود بھی حقیقی تجارت سے روکتا ہے.اس میں جتھہ والے لوگ آگے نکل جاتے ہیں اور دوسرے لوگ گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں.پھر رہن ہے.اس کے متعلق فرمایا کہ وہ باقبضہ ہو اور اس کی تحریر ہو.پھر اسلام نے بیع سلم کا جواز رکھا.عجیب بات ہے کہ آج کل کے مسلمان سود تو لیتے ہیں مگر بیع سلم کو ناجائز قرار
Page 107
دیتے ہیں.حالانکہ اسلام نے سود کے مقابلہ میں بیع سلم کو جائز قرار دیا ہے.آج کل سود کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو بنکوں کا سود ہے اس کے لینے میں کیا حرج ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے.نام خواہ کچھ رکھ لیا جائے وہ بہرحال سود ہے اور اس کا لینا ناجائز اور حرام ہے.اسی طرح اسلام نے تجارت کے اور کئی اصول مقرر کئے ہیں جن کی پابندی تجارتی ترقی کے لئے نہایت ضروری چیز ہے.یہ مسلمانوں کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ بنک جاری ہو گئے جن کو اب ایک دم بند نہیں کیا جا سکتا.اگر آج بنک بند ہو جائیں تو ملک کا دیوالہ نکل جائے.اگر مسلمان شروع سے ہی بیع سلم کو جاری رکھتے تو ان پر بنکوں کی حکومت نہ ہوتی.لیکن عقل کے ساتھ اب بھی کئی ایسے طریق معلوم کئے جا سکتے ہیں جن سے تجارت جاری رہے پہلے بھی لوگ تجارت کرتے تھے اور مسلمانوں میں بڑے بڑے تاجر پائے جاتے تھے اور وہ سود کے بغیر ہی تجارت کرتے تھے.بنکوں کا اس وقت رواج نہ تھا.پھر زمینداریاں ہیں.ان کے متعلق بھی اسلام نے بڑے بھاری قوانین مقرر کئے ہیں.مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز پکنے سے پہلے نہ بیچی جائے(بخاری کتاب البیوع باب بیع الثمار قبل ان یبد و صلاحھا) کیونکہ اس طرح دھوکا ہو جاتا ہے.ہوائیں چلتی ہیں اور پھل گر جاتا ہے یا غلہ کم ہو جاتا ہے خصوصاً باغوں کے متعلق آپ نے حکم دیا کہ پھل پکنے سے پہلے نہ بیچا جائے سوائے اس کے کہ نیچے والی زمین بھی خریدار کو ہی دے دی جائے تاکہ وہ زراعت کر کے کسر پوری کر لے.بہر حال پھل کو پکنے سے پہلے بیچنا منع ہے.پھر زراعت کے متعلق فرمایا وَاٰتُوْا حَقَّہٗ یَوْمَ حَصَادِہٖ(الانعام:۱۴۲) اور اس کی کٹائی کے وقت اس کا حق ادا کرو.اگر پہلے غرباء کا حق ادا کرو گے تب وہ فصل تمہارے لئے جائز ہو گی ورنہ نہیں.پھر دوسرے کے کھیت سے پانی لے جانے کا مسئلہ ہے.اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہاری زمین میں سے پانی لے جانا چاہے تو اسے مت روکو(بخاری کتاب المساقاۃ باب سکر الانـھار) اگر زمین میں سے دوسرے کو پانی لے جانے سے روکا جائے تو اس صورت میں آبادی تباہ ہو جاتی ہے.پھر شادی بیاہ ہے.اسلام نے اس کے متعلق بھی کئی اصول مقرر کئے ہیں.مثلاً عورت کا مہر مقرر کرنا اور پھر عورت کو شادی سے پہلے دیکھنا.تاکہ بعد میں جو فتنے پیدا ہو سکتے ہیں وہ نہ ہوں.شادی کے موقعہ پر جب سب باتیں رشتہ داروں میں طے ہو جائیں تو لڑکی کو دیکھ لینا بہت سے فتنوں کا سدّ باب کر دیتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک نوجوان نے کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہی لڑکی والوں کے سب حالات اسے پسند تھے.اس نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ مجھے اور تو سب باتوں سے اتفاق ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں لڑکی کو بھی دیکھ لوں.اس وقت پردہ کا حکم نازل ہو چکا تھا.لڑکی کے باپ نے کہا میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا.وہ
Page 108
نوجوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے عرض کیا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرناچاہتا ہوں اور تو مجھے سب باتیں پسند ہیں میں صرف لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں میں نے لڑکی کے باپ سے اس کا ذکر کیا تھا مگر اس نے لڑکی دکھانے سے انکار کر دیا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے.شادی کے متعلق اگر سب باتیں طے ہو گئی ہیں تو تم لڑکی کو دیکھ سکتے ہو.وہ نوجوان پھر گیا اور لڑکی کے باپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا.اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو گا مگر میری غیرت یہ برداشت نہیں کر تی خواہ تم شادی کرو یا نہ کرو.میں تمہیں لڑکی دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا.یہ باتیں اندر لڑکی بھی سن رہی تھی جب اس کے باپ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو گا مگرمیری غیرت یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تو وہ پردہ ہٹا کر باہر آگئی اور لڑکے سے مخاطب ہو کر کہنے لگی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو تو میرا باپ کون ہے جو اس میں روک بنے.میں سامنے کھڑی ہوں تم مجھے دیکھ لو.اس چیز کا اس نوجوان پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے نظریں نیچی کر لیں اور اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا اور بولا کہ جس لڑکی کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں اپنے باپ کی محبت کو بھی ٹھکرا سکتی ہے میں اس سے بن دیکھے ہی شادی کر نا چاہتا ہوں.چنانچہ اس نے بن دیکھے ہی اس سے شادی کر لی.غرض ایک طرف اسلام نے پردہ رکھ کرمسلمانوں کو ان فتنوں سے بچایا ہے جو عورت کی وجہ سے پیدا ہو سکتے تھے تو دوسری طرف اندھا دھند شادی کرلینے سے جو خرابیاں پید اہو سکتی ہیں مثلاً رنگ، نقش اور شکل کی وجہ سے ان کو یہ کہہ کر دور کر دیا کہ شادی سے پہلے اگر لڑکی کو دیکھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں.پھر حکومت کے حقوق ہیں.قرآن کریم نے ان کو بھی بیان کیا ہے.حاکم کو کیا کیا اختیار ہوتے ہیں.کس حد تک وہ اپنی رعایا کو حکم دے سکتا ہے اور کس جگہ وہ حکم نہیں دے سکتا.یہ تمام قواعد اسلام نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں.پھر اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ حکومت انتخابی ہونی چاہیے.دنیا کے کسی اور مذہب نے انتخابی حکومت کو پیش نہیں کیا.پھر اسلام نے حاکم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پبلک کی رائے کا احترام کرے.ہاں اگر اس رائے سے دین یا ملک پر کوئی زد پڑتی ہو تو وہ اس کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتا ہے.بعض حکمران کہہ دیتے ہیں کہ ہم پبلک کے منتخب شدہ ہیں.اس لئے ہمیں رائے لینے کی ضرورت نہیں.اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا.اس کے نزدیک پھر بھی ایک کمیٹی بنانی پڑے گی جو مشورہ دے گی اور اس کمیٹی کی اکثریت کی رائے کا وہ حاکم پابند ہو گا.سوائے اس کے کہ وہ کسی مشورہ کومصلحت کے خلاف سمجھے تب وہ اس کمیٹی کے مشورہ کے خلاف بھی فیصلہ کر سکتا ہے.یہ صاف
Page 109
بات ہے کہ جب حاکم پبلک کا منتخب شدہ ہو گا تو بلاوجہ ان کی رائے کے خلاف نہیں چلے گا.وہ اسی وقت ان کی کثرت رائے کو رد کرے گا جب وہ اس تجویز کو قومی اور ملکی مفاد کے خلاف سمجھے گا.اور ایسا قدم وہی شخص اٹھائے گا جو بڑا دیانتدار او رخدا رسیدہ ہو.غرض اسلام نے مشورہ کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شَاوِرْھُمْ فِی الْاَمْرِ ( اٰلِ عمران:۱۶۰) تُو ان سے اہم امور میں مشورہ لے.اور یہ چیز کسی دوسرے مذہب میں نہیں پائی جاتی.ڈیماکریسی جس کے آج جمہوریت والے دعوے دار ہیں اس کو درحقیقت صحیح معنوں میں اسلام نے ہی قائم کیا ہے اور اس میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا.اسلام کی دشمنوں کے متعلق تعلیم اب ہم اسلام کی اس تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں جو اس نے دشمنوں کے متعلق دی ہے.اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی دنیا کی ہدایت کے لئے انبیاء آتے ہیں تو بعض لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں اور بعض ان کے دشمن بن جاتے ہیں.یہ دوستی اور دشمنی کا سلسلہ صرف انبیاء کی جماعتوں سے مخصوص نہیں.سیاسی جماعتوں کو ہی لے لو بعض قومیں ان کی دوست ہوں گی اور بعض دشمن بن جائیں گی.لیکن کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے دوست اور دشمن دونوں کے حقوق بیان کئے ہوں.صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے دوستوں کے متعلق بھی قواعد بیان کئے ہیں اوردشمنوں کے متعلق بھی قواعد بیان کئے ہیں.تورات میں آتا ہے کہ جب تُو اپنے دشمن کے گھرمیں گھسے تو تُو تمام بالغ مردوں کو قتل کر دے اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لے.بلکہ بعض حالات میں تو یہاں تک حکم ہے کہ ان کے جانور بھی ذبح کر دیئے جائیں(استثناء باب ۲۰ آیت۱۰ تا ۱۶) گویا اس تعلیم میں تشدد کی انتہا ہے لیکن اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ نہایت ہی منصفانہ اور اعلیٰ درجہ کی ہے.مثلاً لڑائی کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَ قَاتِلُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَکُمْ (البقرۃ:۱۹۱) تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں.جو شخص تمہارے مقابلہ میں تلوار نہیں اٹھاتا تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم اس سے لڑو اور اس پر تلوار اٹھاؤ.پھر ان لڑنے والوں کو بھی اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ کسی عورت پر وار کریں خواہ وہ عورت جنگ میں شامل ہی کیوں نہ ہو سوائے نہایت اہم استثنائی حالات کے.چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے میدانِ جنگ میں دیکھا کہ کفار میں سے ایک شخص لوگوں کو لڑائی کے لئے بھڑکا رہا ہے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے اور ان کو قتل کرنے کے لئے جوش دلاتا ہے.چنانچہ آپ اس کی طرف بڑھے اور چاہا کہ اس پر وار کریں مگر ابھی آپ نے وار نہیں کیا تھا کہ آپ نے محسوس کیا کہ وہ عورت ہے جومردوں کے لباس میں ملبوس ہے.آپ فوراً واپس آگئے.ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا اسے چھوڑ کیوں دیا.انہوں نے کہا میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ
Page 110
ایک عورت ہے جو مردوں کے لباس میں ملبوس ہے اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس عورت پر وار کروں.(السیرۃ الحلبیہ غزوہ اُحد)حالانکہ وہ عورت کفار کو لڑائی پر برانگیختہ کر کے کئی مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکی تھی مگر اس صحابی نے اسے کچھ نہیں کہا اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر تلوار اٹھانے سے منع فرمایا ہے.اسی طرح احادیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ جنگ کامعائنہ فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک عورت کی لاش دیکھی.صحابہ ؓ کہتے ہیں اس عورت کی نعش دیکھ کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جس نے بھی یہ فعل کیا ہے اس نے ناپسندیدہ فعل کیا ہے ایسا ہر گز نہیں کرنا چاہیے.(بخاری کتاب الجہاد باب قتل النساء فی الحرب) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر دشمن کے مقابلہ کے لئے بھجواتے تھے تو اسے ہدایات دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جنگ کرو اور بد دیانتی نہ کرو اور دھوکہ بازی سے کام نہ لو اور نہ کسی دشمن کے اعضاء کاٹو اور نہ کسی نابالغ کو قتل کرو اور نہ عورتوں کو قتل کرو اور نہ عبادت گاہوں میں بیٹھنے والوں کو قتل کرو اور نہ کسی بڈھے کمزور کو قتل کرو اور نہ چھوٹے بچہ کو اور نہ کسی اور بچہ کو اور نہ کسی بھی عورت کو (ابو داؤد کتاب الـجھاد باب فی دعاء المشـرکین) گویا اسلام نے دشمن کے حقوق کو بھی قائم کیا اور اس کے ساتھ بھی انصاف مدّ ِنظر رکھا.میرے نزدیک اس رحم دلی کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں مل سکتی.اب تو انٹرنیشنل لاء INTERNATIONAL LAW جاری ہو گیا ہے جس کی بنا پر بہت سے اصول وضع کر لئے گئے ہیں.لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ سیاسی قواعد ابھی نہ بنے تھے اور کوئی شخص اس نظام کو نہیں جانتا تھا اس وقت کس نے دنیا کو ان زرّیں ہدایات سے نوازا اور کس نے اسے وحشت اور بربریت کے دائرہ سے نکال کر انسانیت اور مؤاخات کا درس دیا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر جہاد کے لئے جاتے تو حملہ سے پہلے آپ ٹھہر جاتے تاکہ دشمن کو آپ کی آمد کا پتہ لگ جائے اور تا ایسا نہ ہو کہ دشمن سے دھوکا ہو جائے اور اس کی بے خبری میں اس پر حملہ ہو جائے.چنانچہ آپ صبح ہو جانے پر حملہ کرتے اور اگر دشمن کی طرف سے اذان کی آواز آتی تو حملہ نہ کرتے لیکن اگر اذان کی آواز ادھر سے نہ آتی تب صبح ہو جانے پر حملہ کرتے تاایسا نہ ہو کہ کوئی دوست نقصان اٹھائے( مسلم کتاب الصلٰوۃ باب الامساک عن الاغارۃ علٰی قومٍ) آج کل لوگ شب خون مارتے اور اچانک حملہ کرتے ہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان بھی بعض دفعہ شب خون مارتے تھے لیکن شب خون مارنے میں وہ پہل نہیں کرتے تھے.جب دشمن پہل کر دیتا تو جوابی طور پر وہ ایسی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے بہرحال ابتدائی قدم مسلمانوں کی طرف سے نہیں اٹھتا تھا.کیونکہ
Page 111
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح ہدایات تھیں کہ رات کو اور بے اطلاع حملہ نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، پادریوں اور دنیا چھوڑ کر عبادت کرنے والے لوگوں کو قتل نہیں کرنا جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو قتل نہیں کرنا صرف جنگ میں شامل ہونے والوں سے لڑائی کی جائے.پھر اسلام نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ اعلان جنگ کے بغیر کسی قوم سے لڑائی کرنا جائز نہیں.اب تو انٹرنیشنل لاء بھی اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ اعلانِ جنگ ضرور ہونا چاہیے مگر سب سے پہلے یہ اصول اسلام نے ہی مقرر کیا ہے کہ جب تمہارے ہمسایہ میں کوئی قوم رہتی ہو اور اس سے تمہارے معاہدات ہوں تو فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ (الانفال:۵۹) پہلے اعلان کردو اور اس قوم کو اطلاع دو کہ اب پیش آمدہ حالات کی وجہ سے ہماری تمہارے ساتھ صلح نہیں رہ سکتی.تاکہ اسے موقع مل جائے کہ وہ اس کا ازالہ کر سکے اور اگر وہ ازالہ نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی کرو.پھر یہ بھی اسلامی قانون ہے کہ جب دشمن ہتھیار پھینک دے تو تم بھی لڑائی بند کردو.قرآن کریم میں آتا ہے اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَھَا (الانفال:۶۲) کہ جب کوئی قوم تم سے صلح کرنا چاہے تو تم انکار مت کرو.اعلانِ صلح کے بعد اس سے جنگ کرنا جائز نہیں.اسی طرح غیر حکومتوں کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی اسلام نے ایسے قوانین مقرر کئے ہیں جن کا کوئی مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا.مثلاً اسلام نے حکومتوں کے آپس کے اختلافات کو دور کرنے کے لئے بعض اہم اصول تجویز کئے ہیں.جو اتنے مکمل ہیں کہ ان کا مقابلہ نہ پہلی لیگ آف نیشنز کر سکتی تھی اور نہ اب جو یونائیٹڈ نیشنز کی انجمن بنی ہے یہ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے کیونکہ قرآن کریم کے مقرر کردہ اصولوں کو نہ پوری طرح اس پہلی انجمن نے اخذ کیا اور نہ موجودہ انجمن ان کو اختیار کر رہی ہے (اس کا تفصیلی ذکر میں نے اپنی کتاب ’’احمدیت‘‘میں کیا ہے)قرآن مجید میں آتا ہے اِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا١ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ١ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا١ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (الحجرات:۱۰) یعنی جب دو قومیں آپس میں لڑ پڑیں تو دوسری حکومتوں کوچاہیے کہ وہ ان دونوں پر دباؤ ڈالیںاو ران کے آپس کے اختلافات کو دور کریں اور اگر فیصلہ ہو جانے کے بعد دونوں میں سے کوئی قوم اس فیصلہ کو ماننے سے انکار کر دے اور دوسری قوم پر حملہ کر دے تو پھر سب حکومتوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہ طور پر اس پر لشکرکشی کریں تا وہ لڑائی سے رک جائے اور اس فیصلہ کو تسلیم کر لے جو مختلف اقوام کے نمائندوں نے کیا ہے اور اگر وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے لڑائی چھوڑ دے تو صلح کرانے والی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا پہلا فیصلہ ہی نافذ کریں.دوسری حکومت سے
Page 112
کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں اور اس کو لوٹنے کی کوشش نہ کریں.یہی کافی ہے کہ دنیامیں امن قائم ہو گیا.جب لیگ آف نیشنز قائم ہوئی ان دنوں میں انگلستان گیا ہوا تھا.میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہو گی.کیونکہ قرآن کریم نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب دو قوموں میں اختلاف ہو جائے اور ان میں سے کوئی تمہارا فیصلہ نہ مانے تو باقی سب حکومتیں اس پر مل کر لشکر کشی کردیں.لیکن لیگ آف نیشنز میں اس قسم کی لشکر کشی کی کوئی صورت نہیں رکھی گئی اور اب جو یونائیٹڈ نیشنز کی انجمن بنی ہے اس کے متعلق بھی میں وہی کچھ کہتا ہوں کہ یہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو گی جب تک کہ وہ اپنے قواعد نہ بدلے.کیونکہ اس میں بھی وہ شرائط پورے طور پر نہیں پائی جاتیں جو اسلام نے تجویز کی ہیں.اس میں لشکر کشی کے لئے اختیارات تو رکھے ہیں مگر پھر بھی کوئی معین فیصلہ نہیں کیا گیا اور پھر اس میں بعض حکومتوں کو شامل کیا گیا ہے اور بعض کو شامل نہیں کیا گیا.مثلاً سپین کی حکومت ہے اس کو انہوں نے شامل نہیں کیا.جب وہ کہتی تھی کہ میں تمہارے احکام ماننے کے لئے تیار ہوں تو چاہیے تھا کہ اسے بھی شامل کر لیتے.مگر ایسا نہیں کیا گیا.اسی طرح بعض کو کم اختیارات دئیے گئے اور بعض کو زیادہ.گویا اب بھی ایسے امتیازات رکھے گئے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا.اس لئے یہ بھی کامیاب نہیں ہو گی.آج یوروپ بڑا خوش ہے کہ اس نے ایسا قانون مقرر کر دیا ہے.مگر اسے کیا معلوم کہ وہ قانون جو ہر لحاظ سے مکمل اور قابل عمل ہے آج سے تیرہ سو سال پہلے کی نازل شدہ قرآنی آیات میں موجود ہے.اگر اس قانون پر عمل کیا جائے تو وہ جھگڑے جنہوں نے آج دنیا کو ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گرا رکھا ہے بالکل دور ہو جائیں اور دنیا ایک بار پھر امن اور اطمینان کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے.اوپر میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ اسلام کی اس تعلیم کا حصہ ہے جو اس نے بنی نوع انسان کے متعلق پیش کی ہے اور جس کی مثال کوئی اور مذہب پیش نہیں کر سکتا.اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام نے صرف انسانوں کے متعلق ہی تعلیم نہیں دی بلکہ اس نے جانوروں کا بھی خیال رکھا ہے اور ان سے بھی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمِ (الذَّاریٰت:۲۰ ) تمہارے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے.محروم کے معنے انسانوں میں سے ان لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو مانگ نہیں سکتے مگر زیادہ تر اس سے اشارہ ان بے زبان جانوروں کی طرف ہے جو مانگ ہی نہیں سکتے.مثلاً بلی، کتا اور دوسرے جانور.اس میں شبہ نہیں کہ بعض غیر قومیں جانوروں سے بڑا پیار کرتی ہیں.مثلاً انگریز ہیں وہ کتے کی بڑی قدر کرتے ہیں.ان کے نزدیک ایک کتا دس ایشیائیوں سے بھی بہتر ہوتا ہے مگر کتے سے پیار وہ اس لئے نہیں کرتے کہ انہیں
Page 113
حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے بلکہ وہ اپنے شوق کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں.اس کے مقابلہ میں اسلام نے جانوروں کے متعلق مستقل احکام دیئے ہیںاور جو مسلمان ان سے حسن سلوک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کرتاہے.احادیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے سزا دی گئی.اس عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اسے کھانے پینے کے لئے کچھ نہ دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی.خدا تعالیٰ نے اس فعل کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا (بخاری کتاب الانبیاء باب حدیث الغار) اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کہیں جارہا تھا کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا لیکن وہ پانی تک نہیں پہنچ سکتا تھا.اس شخص نے سوچا کہ جس طرح میں پیاسا تھا یہ بھی پیاسا ہے اور نشیب جگہ میں اتر کر جُوتی میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلایا.اللہ تعالیٰ اس کے اس فعل سے خوش ہوا اور اس نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے.(بخاری کتاب الادب باب رحمۃ الناس والبھائم ) ایک صحابی کہتے ہیں قَالَ کُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ سَفَرِہٖ فَانْطَلَقَ لِـحَاجَتِہٖ فَرَاَیْنَا حُـمَّرَۃً مَعَھَا فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَیْـھَا فَـجَاءَتِ الْـحُمَّرَۃُ فَـجَعَلَتْ تَفْرُشُ فَـجَآءَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَـجَّعَ ھٰذِہٖ بِوَلَدِھَا رُدُّوْا وَلْدَھَا اِلَیْـھَا(ابو داؤد کتاب الجھاد باب فی کراھیۃ حرق العدو با لنار)ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے.آپ کسی کام کے لئے اِدھر اُدھر ہوئے تو ہم نے ایک فاختہ کو دو بچوں سمیت دیکھا.ہم نے اس کے بچے پکڑ لئے فاختہ نے زمین پر لوٹنا شروع کیا.اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور اسے دیکھ کر فرمایا اس فاختہ کو کس نے اس کے بچہ کے ذریعہ سے دکھ پہنچایا وہ شخص فوراً اس کا بچہ واپس کرے.اسی طرح احادیث میں آتا ہے اَنَّ النَّبِیَّ صلی اللہ علیہ وسلم مُرَّ عَلَیْہِ بِـحِمَارٍ قَدْ وُسِـمَ فِیْ وَجْھِہٖ فَقَالَ اَمَا بَلَغَکُمْ اَنِّیْ قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَـمَ الْبَـھِیْمَۃَ فِیْ وَجْھِھَا اَوْ ضَـرَبَـھَا فِیْ وَجْھِھَا فَنُـھِیَ عَنْ ذَالِکَ (ابو داؤد کتاب الجہاد باب النّھی عن الوسم فی الوجہ والضرب فی الوجہ) کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کے منہ پر لوگوں کو نشان لگاتے دیکھا.آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے منہ پر نشان لگانے والے یا منہ پر مارنے والے کو برا قرار دیا ہے پس ایسا نہ کیا کرو.غرض اسلام نے صرف انسانوں کے حقوق کی ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق تک کی حفاظت کی ہے.حکمت تیسری بات جو دعائے ابراہیمی کے جواب میں مذکورہ بالا آیت میں بتائی گئی ہے یہ ہے کہ یہ حکمت سکھاتا ہے.حکمت کے معنے عربی زبان میں وہی ہیں جو انگریزی میں فلسفہ کے ہیں.جس طرح ہسٹری اور چیز ہے
Page 114
اور فلاسفی آف دی ہسٹری اور چیز ہے.فیلالوجی اور چیز ہے اور فلاسفی آف دی فیلالوجی اور چیز ہے.لاء اور چیز ہے اور فلاسفی آف دی لاء اور چیز ہے.اسی طرح احکام اور چیز ہیں اور ان کی حکمت اور چیز ہے.ایک چیز واقعات اور تفصیلات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور دوسری اس کے پس منظر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.مثلاً نماز کیا ہے ایک خاص رنگ کی عبادت ہے جو بعض شرائط کے ساتھ مشروط ہے.یعنی وضو کیا، نیت باندھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، سجود کئے، کچھ ٹکڑے قرآن کریم کے پڑھے، دعائیں کیں اور سلام پھیر دیا.مگر یہ تو ہے دعا لیکن اس کا فلسفہ یا حکمت الگ شے ہے.اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ نماز کیا شے ہے تو ہم اسے نماز پڑھنے کی تفصیل بتائیں گے لیکن اگر کوئی پوچھے کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے تو ہم اسے یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم اس طرح وضو کرتے ہیں اور پھر قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں بلکہ ہم یہ بتائیں گے کہ نماز کیوں مقرر کی گئی ہے اس کے فوائد کیا ہیں.اس کا مقصد کیا ہے.اس کی غرض کیا ہے.پس کسی چیز کا فلسفہ وہ چیز ہے جس میں اس کے موجب اوراس کی غرض و غایت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے یا فلسفہ ان محرکات کو کہتے ہیں جو ماضی میں ہوتے ہیں.یعنی فعل سے پہلے وقوع پذیر ہوتے ہیں یا ان نتائج کو کہتے ہیں جو فعل کے بعد پیدا ہوتے ہیں.مثلاً ایک شخص نے احسان کیا اس کا ہم شکریہ ادا کریں گے.تو شکریہ کا محرک پہلے موجود ہو گا.لیکن جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو مزدوری پہلے ہو گی اور اس فعل کا نتیجہ یعنی اجرت بعد میں ملے گی.پس کبھی غایت انسان کے لئے محرک بن جاتی ہے او رکبھی ابتداء محرک بن جاتی ہے.فلاں چیز کیوں ہے اور کس لئے ہے اس کا جو جواب ہو گا وہ فلسفہ کہلاتا ہے.اسی طرح یہ بتانا کہ فلاں کام کے اندر کیا کیا مصلحتیں پوشیدہ ہیں کیا کیا خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اس کا حکم دیا گیا ہے یا اسے اختیار کیا گیا ہے.یہ سب حکمت کے ماتحت آتے ہیں.کتب الہامیہ میں قرآن کریم ہی وہ پہلی کتاب ہے جس نے یہ اصول پیش کیا ہے کہ ہر کام حکمت کے ماتحت ہونا چاہیے اور یہ صرف انسان کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ خدا تعالیٰ بھی کوئی کام بلاوجہ نہیں کرتا.اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مَا لَکُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰہِ وَقَارًا (نوح:۱۴) تمہیں کیا ہو گیاکہ تم خدا تعالیٰ کی حکمت کو تسلیم نہیں کرتے.تم اپنے متعلق تو یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ کہا جائے کہ تم بغیر کسی مقصد اور مدعا کے کام کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے.اسی لئے خدا تعالیٰ کا ایک نام حکیم بھی ہے اور اس نے ہر جگہ اپنے احکام کی وجہ بیان کی ہے صرف یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں خدا ہوں اس لئے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیونکہ انسان دلائل کا محتاج ہے.اگر خدا تعالیٰ حکم دیتا کہ فلاں کام کرو اور پھر اس کی وجہ بیان نہ کرتا تو انسانی ایمان بہت حد تک کمزور رہتا اور وہ کہتا کہ خدا تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے میری سمجھ
Page 115
میں تو اس کی وجہ نہیں آئی.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام حکیم رکھا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس کی کوئی غرض نہ ہو.مَا لَکُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰہِ وَقَارًا میں اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم سمجھ دار ہو تو تم کوشش کرتے ہو کہ تمہارا ہر کام معقول ہو اور کسی حکمت کے ماتحت ہو.لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ اندھا دھند کام کرتا چلا جاتا ہے.تم کہتے ہو کہ اس نے ایک بیٹا بنا لیا ہے.آخر غور کرو کہ اسے بیٹا بنانے کی ضرورت کیا تھی.بیٹے کی خواہش تو انسان کے دل میں اس لئے ہوتی ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کی یاد کو قائم رکھنے والا کوئی وجود اس دنیا میں ہو.کیا نعوذباللہ خدا تعالیٰ نے مر جانا تھا کہ اس نے بیٹا بنا لیا.پھر دوسری وجہ اس خواہش کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جتھے کی ضرورت ہوتی ہے وہ خیال کرتا ہے کہ آٹھ نو بیٹے ہوں گے تو میری مدد کریں گے کیا نعوذباللہ اللہ تعالیٰ کمزور تھا اور اسے دشمنوں سے خطرہ تھا یا اپنا کام اکیلے چلانا اس کے لئے مشکل تھا کہ اس نے بیٹا بنا لیا.آخر غور کرو اور سوچو کہ تم تو اپنے کام کے لئے حکمتیں تلاش کرتے ہو مگر خدا تعالیٰ کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ وہ اندھا دھند اور بلاوجہ کام کرتا ہے.کیا یہ معقول بات ہے؟ فلسفۂ گناہ کا بیان اب میں چند موٹی موٹی مثالیں دیتا ہوں جن سے یہ ظاہر ہو گا کہ قرآن کریم نے کس طرح اپنے تمام احکام کی بنیادفلسفہ پر رکھی ہے.اسلام نے بنی نوع انسان کو مختلف قسم کی بدیوں سے روکا ہے اور قرآن کریم اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے.مگر سوال یہ ہے کہ گناہ کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے.قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ بدی کے کچھ دروازے ہوتے ہیں پہلے ان دروازوں کو بند کرو پھر تم اس بدی پر غالب آسکو گے.مسیح ناصری ؑکہتے ہیں کہ کسی عورت کی طرف بد نیتی سے نگاہ مت ڈال.سوال یہ ہے کہ بد نیتی تو اسی لئے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کسی ایسی عورت کی طرف دیکھتا ہے جو خوبصورت ہوتی ہے.دیکھنے سے پہلے تو بد نیتی پیدا نہیں ہوسکتی اگر دیکھنے سے پہلے بد نیتی پیدا نہیں ہو تی تو پھر اس کے کیا معنے ہوئے کہ تُو کسی غیر محرم کو بد نظری سے نہ دیکھ اور اگر اس کے کوئی معنے نہیں تو پھر یہ حکم بے فائدہ ہوا.مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ تم کسی غیر محرم عورت کی طرف مت دیکھو.نہ نیک نیتی سے نہ بری نظر سے.تمہیں کیا پتہ کہ وہ تمہارے لئے کشش رکھتی ہے یا نہیں.اگر وہ تمہارے لئے کشش رکھتی ہے تو پھر ناجائز محبت پیدا ہو گی.اس لئے تم اس کا دروازہ ہی بند کردو تاکہ تمہارا دل ہر قسم کی آلودگی سے محفوظ رہے.اسی طرح اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ بدکاری نہ کر بلکہ وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ غیر محرم عورت اور مرد ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں.دوسرے مذاہب کہتے ہیں اکٹھے بے شک ہوجاؤ مگر بدکاری نہ کرو.حالانکہ جب بدی کے سامان موجود ہوں اس وقت بدی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے.اسی
Page 116
طرح دوسرے مذاہب نے کہا ہے کہ تم روپیہ کو ناجائز طورپر خرچ نہ کرو.لیکن جب روپیہ جمع ہو گیا تو وہ خرچ کیوں نہ ہوگا.اسلام کہتا ہے کہ تم روپیہ جمع ہی نہ کرو.جب روپیہ جمع ہی نہ ہو گا تو وہ ناجائز طور پر خرچ بھی نہیں ہو گا.اسلام نے بے شک عورت کو آرائش اور زینت کے لئے تھوڑا سا زیور رکھنے کی اجازت دی ہے مگر اس کا زیورات سے لدا پھندا رہنا اسلامی شریعت کی رُو سے ناجائز ہے.پھر کھانے پینے پر حد بندی لگا دی.فرمایا کُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا (الاعراف:۳۲) کھانے پینے میں اسراف نہ کرو.غرض روپیہ خرچ کرنے کے جو ذرائع تھے ان سے روک دیا.مثلاً کھانے پینے میں اسراف سے روک دیا.زیادہ زیور بنانے سے روک دیا.خود عورت کو کہہ دیا کہ زیادہ آرائش نہ کرو.راگ رنگ اور ناچ گانے سے روک دیا.شراب سے منع کر دیا.غرض لذت کے وہ تمام ذرائع جن سے اسراف پیدا ہوتا ہے اسلام نے ممنوع قرار دے دیئے.گویا اسلام صرف گناہ سے نہیں روکتا بلکہ گناہ کے دروازہ کو بھی بند کرتا ہے اور اس طرح فلسفۂ گناہ کو لطیف رنگ میں بیان کردیتا ہے.فلسفۂ عبادت اسی طرح عبادات ہیں.ان کا فلسفہ بھی اسلام نے پیش کیا ہے.وہ بتاتا ہے کہ نماز کوئی چٹّی نہیں بلکہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ (العنکبوت:۴۶) نماز اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ یہ انسانوں کو بدیوں سے روکتی ہے.گویا اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ تُو نماز پڑ ھ مگر اس لئے نہیں کہ تیرا خدا چاہتا ہے کہ تُو دس پندرہ منٹ تک اوٹھک بیٹھک کرے بلکہ اس لئے کہ یہ تمہاری اصلاح کا موجب ہے اور یہ بدیوں کو مٹانے والی چیز ہے.یہ مضمون کہ نماز بدیوں سے کس طرح روکتی ہے چونکہ لمبا ہے میں اس جگہ بیان نہیں کرتا.یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن کریم صرف نماز کا حکم نہیں دیتا بلکہ اس حکم کی حکمت اور وجہ بھی بیان کر تا ہے.پھر روزہ کے متعلق فرمایا لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرۃ:۱۸۰) تم روزہ رکھو.اس لئے کہ اس سے اتقاء پیدا ہوتا ہے اور جب تم میں اتقاء پیدا ہو جائے گا تو تم ہر قسم کی خرابیوں سے بچ جاؤ گے.روزہ کی حالت میں انسان کچھ وقت کے لئے بھوکا رہتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس پید اہوتا ہے کہ جب دو وقت کا کھانا مل جانے کے باوجود مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اس شخص کا کیاحال ہو گا جسے کئی کئی وقت کے فاقے برداشت کرنے پڑتے ہیں.اس طرح غربا پروری کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جو قومی ترقی کے لئے ایک نہایت ضروری چیز ہے.غرض اسلام نے عبادات کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان کی حکمت بھی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ تمام عبادات انسان کے فائدہ کے لئے مقرر کی گئی ہیں.اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت منوانے کے لئے نہیں کیں.پھر قرآن کریم کی ایک اور خوبی جو اپنے اندر بڑی بھاری حکمت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام احکام میں اعتدال کو مدّ ِنظر رکھا ہے تاکہ انسانی نفس پر ایسا
Page 117
بوجھ نہ پڑے جو اس کے ملال کا موجب بن جائے.اس نے روٹی کھانے میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے.اس نے پانی پینے میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نماز بھی پڑھو تو اس میں اعتدال سے کام لو.روزہ بھی رکھو تو اس میں بھی اعتدال سے کام لو.مال بھی خرچ کرو تو اس میں بھی اعتدال سے کام لو.چنانچہ جہاں اسلام نے مال جمع کرنے سے منع فرمایا وہاں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم ایسے بھی نہ بنو کہ بالکل خالی ہاتھ ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں حسرت ہو کہ ہائے میں کنگال ہو گیا.جہاں روزے کا حکم دیا وہاں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہر روز روزہ رکھنا منع ہے.احادیث میں آتا ہے اِنَّ عَبْدَ اللہِ ابْنَ عَـمْرٍو قَالَ اُخْبِرَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَنِّیْ اَقُوْلُ وَاللہِ لَاَصُوْمَنَّ النَّـھَارَ وَلَاَقُوْمَنَّ اللَّیْلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَہٗ قَدْ قُلْتُہٗ بِاَبِیْ اَنْتَ وَ اُمِّیْ قَالَ فَاِنَّکَ لَا تَسْتَطِیْعُ ذَالِکَ فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَ قُـمْ وَ نَمْ وَ صُـمْ مِنَ الشَّھْرِ ثَلَاثَۃَ اَیَّامٍ فَاِنَّ الْـحَسَنَۃَ بِعَشْـرِ اَمْثَالِھَا وَ ذَالِکَ مِثْلُ صِیَامِ الدَّھْرِقُلْتُ اِنِّیْ اُطِیْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِکَ قَالَ فَصُمْ یَوْمًا وَ اَفْطِرْ یَوْمَیْنِ قُلْتُ اِنِّیْ اُطِیْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِکَ قَالَ فَصُمْ یَوْمًا وَ اَفْطِرْ یَوْمًا فَذَالِکَ صِیَامُ دَاوُدَ عَلَیْہِ السَّلَامَ وَ ھُوَ اَفْضَلُ الصِّیَامِ فَقُلْتُ اِنِّیْ اُطِیْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذَالِکَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا اَفْضَلَ مِنْ ذَالِکَ.(بخاری کتاب الصوم باب صوم الدھر) یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر وؓ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ عبد اللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور ہر رات عبادت کے لئے جاگا کروں گا.آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس امر کی تصدیق کی.آپ نے فرمایا تم میں یہ طاقت نہیں کبھی روزہ رکھا کرو اور کبھی افطار کیا کرو اور کبھی سویا کرو کبھی عبادت کیا کرو اور مہینہ میں تین دن روزہ رکھنا کافی ہے.کیونکہ ایک نیکی کا دس گنے بدلہ ملتا ہے.اس طرح تیس دن کے روزے پورے ہو گئے اور گویا دائمی روزہ ہو گیا.میں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں.فرمایا ایک دن روزہ رکھو دو دن چھوڑ دو.میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں.فرمایا اچھا پھر ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑدو اور حضرت داؤد ؑ اسی طرح روزے رکھا کرتے تھے.میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا اس سے زیادہ روزے رکھنا اچھا کام نہیں.حضرت عبد اللہ ؓ جب بوڑھے ہوئے تو کہا کرتے تھے کاش میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتا.اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا مجھ پر دو بھر گذرتا ہے(بخاری کتاب الصوم باب حق الجسم فی الصوم).اسی طرح آپ نے فرمایا عیدکے دن روزہ رکھنا، انسان کو شیطان بنا دیتا ہے.(بخاری کتاب الصوم باب صوم یوم الفطر )
Page 118
پھر نماز ہے.آپ نے فرمایا جب سورج سر پر ہو یا سورج چڑھ رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو اس وقت نماز نہ پڑھو(نسائی کتاب الصلوٰۃ باب الساعات الّتی نـھی عن الصلٰوۃ فیـھا و مسند احـمد حنبل مسند بلال وعائشۃ) دراصل اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی وقت ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں انسان کا دماغ فارغ ہو ورنہ وہ بے کار ہو جاتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک بیوی نے جن کا نام زینبؓ تھا چھت کے ساتھ رسہ لٹکایا ہوا ہے.آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ رسہ کیسا ہے؟ تو حضور کو بتایا گیا کہ حضرت زینبؓجب نماز پڑھتی پڑھتی تھک جاتی ہیں تو اس سے سہارا لے لیتی ہیں.آپ نے فرمایا اسے فوراً اتار دو.یہ کوئی نماز نہیں.جب نما زپڑھتے پڑھتے انسان تھک جائے تو اسے چاہیے کہ آرام کرے.(بخاری کتاب التہجد باب ما یکرہ فی التشدید فی العبادۃ) اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حج کی نذر مانی تھی اور اس کے ساتھ بعض اور شرطیں بھی لگائی تھیں.آپ نے دیکھا کہ اسے اس کے لڑکے سہارا دے کر چلارہے ہیں.آپ نے دریافت فرمایا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اس شخص نے حج کی نذر مانی ہوئی تھی اس کو ہم اٹھا کر لے جارہے ہیں تاکہ اس کی نذر پوری ہو جائے.آپ نے فرمایا یہ لغو بات ہے.اللہ تعالیٰ ایسی عبادتوں سے غنی ہے (بخاری کتاب جزاء الصید باب من نذر المشی الی الکعبۃ) اسی طرح آپ کے زمانہ میں غنیمت کے اموال آئے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان اموال کا ایک حصہ غرباء کے لئے مخصوص کر دیا جائے.چونکہ سوال ہو سکتا تھا کہ امراء کو غنیمت میں سے کیوں برابر کا حصہ نہ دیا جائے جبکہ وہ بھی جنگ میں حصہ لیتے ہیں؟ اس کے جواب میں فرمایا كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ (الحشـر:۸) ہم نے غنیمت کا ایک حصہ غرباء کے لئے اس لئے مخصوص کر دیا ہے کہ امراء کے پاس تو پہلے ہی روپیہ ہے.اگر غنیمت کے اموال میں بھی ان کا برابر حصہ رکھا جائے تو ان کے ہاتھوں میں روپیہ جمع ہوتا جائے گا.پس ہر مجاہد کو اس کا حصہ دینے کے بعد ایک حصہ غرباء کے لئے الگ بھی مخصوص کر دیا گیا.پھر اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے ہے جیسے فرمایا وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ (الجاثیۃ:۱۴) زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس نے تمہارے فائدہ کے لئے پید اکیا ہے.یہ نکتہ اسلام نے آج سے تیرہ سو سال قبل بیان کر دیا تھا جبکہ دنیا موجودہ علوم سے بالکل نا آشنا تھی.مگر اب جو تحقیقاتیں ہو رہی ہیں وہ اسلام کے اس پیش کردہ اصل کی سچائی کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرتی چلی جا رہی ہیں اور ایسی ہزار ہا چیزوں کے فوائد ثابت ہو رہے ہیں جن کو پہلے سخت نقصان دِہ سمجھ جاتا تھا یا
Page 119
جن کا کوئی خاص فائدہ معلوم نہیں تھا.مثلاً سانپ ایک زہریلی چیز ہے مگر اس زمانہ میں اس کے زہر سے بھی بڑے بڑے بھاری کام لئے جا رہے ہیں اور اسے سل کے لئے مفید بتایا جاتا ہے.بہاول پور میں ایک مریض کو ڈاکٹروں نے لا علاج سمجھ کر جواب دے دیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ طاقت کے لئے میٹھے کا استعمال کرتا رہے.اس نے اس مقصد کے لئے گنّے کھانے شروع کئے اور وہ تندرست ہو گیا.بعد میں معلوم ہوا کہ ان گنوں کے نیچے کوئی سانپ دفن تھا جس کا اثر گنّوں میں آیا اور ان گنّوں کے استعمال سے اس کا مرض جاتا رہا.ہومیو پیتھی میں یہ زہر ستر سال سے استعمال ہو رہا ہے.میں نے خود بھی کئی مریضوں کو دیا ہے.اور اس نے غیر معمولی فائدہ دیا ہے.پھر سنکھیا کو لے لو اس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے لیکن خدا تعالیٰ نے اسے مارنے کے لئے نہیں بنایا بلکہ بیماروں کو اچھا کرنے کے لئے بنایا ہے.ڈاکٹروں نے اس سے قسم قسم کی دوائیں ایجاد کی ہیں.مثلاً پرانے بخاروں میں جو ہلکے ہلکے رہتے ہوں سنکھیا استعمال ہوتا ہے اور اس سے لاکھوں لاکھ بیمار شفا پاتے ہیں.پھر پاخانہ بظاہر کتنی گندی چیز ہے لیکن کھیت اسی سے پکتے ہیں.میونسپل کمیٹی والے گندے نالوں کو بڑی بڑی قیمتوں پر فروخت کرتے ہیں حالانکہ ہم اسے ردّی اور لغو سمجھتے ہیں.پھر بلغم ہے اس کے ذریعہ مائیکروسکوپ MICROSCOPE سےڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتے ہیں.اگر بلغم نہ آئے تو ڈاکٹر گھبراتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بلغم پیدا کرو تا مرض کی تشخیص ہو سکے.پھر اس سے آٹو ویکسین تیار ہوتی ہے جو دیرینہ امراض کو دور کرنے میں بڑی مفید ثابت ہوئی ہے.پس کوئی چیز اپنی ذات میں بری نہیں بلکہ حالات کے ماتحت وہ بری ہو جاتی ہے اور حالات کے ماتحت اچھی ہوجاتی ہے.اور قرآن کریم نے اس نکتہ کو سائنس کی دریافت سے بہت پہلے بیان فرما دیا تھا.پھر اخلاق فاضلہ کے متعلق فرمایا کہ یہ انسانی فطرت کے صحیح استعمال کا نام ہے.طاقتیں وہی ہوتی ہیں لیکن برے استعمال سے بدی بن جاتی ہے اور اچھے استعمال سے نیکی بن جاتی ہے.مثلاً ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت رکھی گئی ہے جب وہ بغیر اجازت دوسرے کی چیز اٹھائے گا تو وہ چوری کہلائے گی لیکن اپنی چیز اٹھانے کا نام محنت اور مزدوری ہے اور مزدور کو کوئی شخص برا نہیں کہتا.اگر طاقت نہ ہوتی تو ہم کام کیسے کرتے.مگر طاقت کا غیر محل استعمال اسے چور بنا دیتا ہے.غرض اسلام یہ بتاتا ہے کہ فطرت انسانی نیکی پر مبنی ہے صرف اس کاغلط استعمال خرابی پیدا کرتا ہے.جب طبعی قوتوں کو مطابق موقعہ، مطابق ضرورت اور بطریقۂ مناسب استعمال کیاجائے تو وہ اخلاق فاضلہ کہلاتے ہیں.یہ حکمت بھی سوائے اسلام کے اور کسی مذہب نے بیان نہیں کی.تزکیۂ نفوس چوتھی بات جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پایا جانا ضروری تھا اور جس کی التجاء دعا ئے
Page 120
ابراہیمی میں کی گئی تھی وہ تزکیۂ نفوس کا کام تھا.اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے جوا ب میں فرمایا تھا کہ ہم نے ایسا رسول تم میں مبعوث کر دیا ہے جو تمہارے دلوں کو پاک کرتا اور انہیں محبت الٰہی کی آگ سے روشن رکھتا ہے.اب اس جگہ پر فرماتا ہے کہ اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ.وہ تزکیۂ قوم کی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی صرف اسے ہی ہم نے قبول نہیں کیا بلکہ اس قوت میں ہم نے اپنے رسول کو کوثر عطا فرمایا ہے.تزکیہ کی تین اقسام تزکیہ تین قسم کا ہو اکرتا ہے(۱) عمل کا(۲)جذبات کا(۳) فکر کا.یعنی جہاں تک نفس انسانی کی پاکیزگی کا سوال ہے اسے تین قسم کی پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے.اوّل جذبات کی پاکیزگی.کیونکہ سب سے پہلے جذبات ہی رونما ہوتے ہیں.بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جذبات کی وجہ سے ہی وہ تمام کام کرتا ہے.عمل اور فکر کا زمانہ ابھی دور ہوتا ہے.بھوک لگتی ہے تو چیخیں مارتا ہے.ماں کی جدائی پر روتا ہے اور یہ تمام کام اس کے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں.جب وہ چلنا پھرنا شرع کر دیتا ہے تو پھر کچھ عمل شروع ہو تا ہے اور جب وہ بلوغت کے زمانہ تک پہنچتا ہے تو پھر وہ تدبر کرتا، سوچتا اور کچھ نتائج اخذ کرتا ہے اور جب یہ تینوں چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کا جسم بھی اپنی تکمیل حاصل کرلیتا ہے.اوپر جو امور بیان ہو چکے ہیں ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تزکیہ اسلام کی اتباع کا لازمی نتیجہ ہے اور حقیقی تزکیہ صرف اسلام ہی پیدا کر سکتا ہے.حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مذہب کی تعلیم درست ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ ضرور ان کا تزکیہ کرے گا.لیکن اگر مذہب کی تعلیم ہی درست نہ ہو تو پھر اس پر عمل کر کے انسان ضرور ٹھوکر کھائےگا.مثلاً اسلام نے کہا ہے کہ اگر تم عفو میں فائدہ دیکھو تو معاف کر دو اور اگر سزا میں فائدہ دیکھو تو سزا دو.اب جو شخص اس پر عمل نہیں کرتا وہ نہ کرے لیکن جو اس پر عمل کرے گا وہ یقیناً بہترین عمل والا انسان ہو گا لیکن یہودیت کہتی ہے کہ ہر ایک کو سزا دو.ناک کے بدلے ناک،کان کے بدلے کان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اب جو شخص اس تعلیم پر عمل نہیں کرتا وہ نہ کرے.لیکن جو شخص اس تعلیم پر عمل کرے گا وہ ضرور غلطی میں مبتلا ہو گا اور ہزاروں دفعہ وہ ظلم اور تعدی سے کام لے گا.یا مثلاً انجیل کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو.اگر تم سے کوئی کرتہ مانگے تو تم اسے اپنی چادر بھی اتار دو اور اگر تمہیں کوئی ایک میل بیگار لے جانا چاہے تو تم اس کے ساتھ دو میل تک چلے جاؤ.اس تعلیم پر اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو وہ نہ کرے لیکن عمل کرنے والا کئی دفعہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا مثلاً ڈاکو آئیں اور گھر کا مالک اپنا سامان نکال نکال کر ان کے سامنے رکھ دے اور کہے کہ آپ نے غلطی سے یہ سامان تو دیکھا نہیں میں یہ سامان بھی آپ کو دیتا ہوں.تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا؟ملک کا امن
Page 121
تباہ ہو جائے گا.بد امنی کا دور دورہ ہو جائے گا.ہر طرف فساد پھیل جائے گا.ڈاکہ زنی اور چوریوں کے واقعات بڑھ جائیں گے اور لوگ جرائم کے عادی ہو جائیں گے.اس کے ساتھ ہی اسلامی تعلیم یہ بھی ہے کہ مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِہٖ وَ عِرْضِہٖ فَھُوَ شَھِیْدٌ(ریاض الصالحین باب بیان جماعۃ من الشھداء....).جو شخص اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہو امارا جاتا ہے وہ شہید ہے.یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے والی ہے.جب کہیں ڈاکہ پڑے گا سارے شہر والے باہر نکل کر مقابلہ کے لئے آجائیں گے اور ڈاکو آئندہ اس شہر میں آنے کی جرأت نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمجھ لیں گے کہ اس شہر کے لوگ ہو شیار ہیں.پھر جب ہر شخص کو یہ نظر آئے گا کہ اگر وہ اپنے مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہو امارا جائے گا تو شہید ہو گا تو ایسا شخص ڈرے گا کیوں.وہ سمجھے گا کہ اگر میں مقابلہ کرتے کرتے مارا گیا تو شہید ہو جاؤں گا اور اگر بچ گیا تو مال بھی محفوظ رہے گا اور عزت بھی قائم رہے گی غرض امن اگر قائم ہو گا تو اسلام کی تعلیم کے مطابق ہو گا.عیسائیوں اور یہودیوں کی تعلیم کے مطابق نہیں ہو گا.اسی طرح یہودیوں کی کتاب میں یہ حکم ہے کہ جب تو کسی ملک پر حملہ کرے اور اسے فتح کر لے تو تُو اس ملک کے تمام مردوں کو مار ڈال حتی کہ جانوروں کو بھی مار ڈال اور اس ملک کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لے.یہ کیسی وحشیانہ تعلیم ہے اور کیا اس سے ملک میں امن قائم ہوسکتا ہے؟جب یہ ان کے سارے مرد مار دیں گے اور ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیں گے تو یہ صاف بات ہے کہ جب ان کا داؤ چلے گا وہ بھی ایسا کریں گے.یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کے اندر ہر چیز کا ردّ عمل پید اہو تا ہے اگر اس تعلیم کے مطابق یہودی کسی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو جب دوسری قوم کا غلبہ ہو گا وہ بھی ان سے ویسا ہی سلوک کرے گی.اس کا نتیجہ کیا ہو گا؟ کھیتی باڑی تباہ ہو جائے گی، فصلیں بر باد ہو جائیں گی، قوم کے افراد کم ہوجائیں گے،محنت کرنے والے کہیں نہیں ملیں گےکیونکہ سب لوگ مارے جاچکے ہوں گے لیکن اس کے مقابلہ میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر بحالت مجبوری تمہیں لڑنا بھی پڑے تو قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ( البقرۃ:۱۹۱) تم صرف ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہوں.وہ لوگ جو قانون ملک اور اخلاق فاضلہ کو بالائے طاق رکھ دیں تم ان سے بے شک لڑو لیکن جو لڑائی میں شامل ہی نہیں ان کو مارنے کا کیا مطلب؟ جو تمہیں مارنا چاہتا ہو اور تم پر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو تم بھی مارو.اگر وہ مر جائے گا تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تمہیں مارنا چاہتا تھا لیکن جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑائی میں شامل نہیں ہوئے خواہ وہ اس قوم کے ہی افراد ہوں جس سے لڑائی ہو رہی ہے وہ کیوں مارے جائیں.وہ تمہارے مقابلہ پر نہیں آئے، وہ تم سے لڑے نہیں، تمہارے مقابلہ پر انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی.پھر ان کو مارنے کا کیا مطلب؟پھر اسلام کہتاہے عورتوں اور بچوں کو بھی نہ مارو، کمزوروں کو بھی نہ مارو.تاریخ سے ثابت
Page 122
ہو تا ہے کہ کسی جنگ میں بھی نہ سارے صحابہؓ لڑے اور نہ ہی سارے کفار لڑے.اس وقت عرب کی دو تین لاکھ آبادی تھی مگر تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ لڑنے والے صرف چند ہزار افراد ہوتے تھے.اگر صحابہؓ فتح کے بعد سب کفار کو ماردیتے تو عرب میں چند گنتی کے ہی مسلمان رہ جاتے اور اگر سارے کفار مر جاتے تو اسلام کہاں پھیلتا.پس یہودیت کی تعلیم ناقص تعلیم ہے.صرف اسلام کی تعلیم ہی ایسی ہے جو دنیامیں حقیقی امن قائم کرنے والی ہے.پھر یہیں تک بس نہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ نے سب دشمنوں کو معاف فرما دیا.سوائے سات آدمیوں کے جنہوں نے شرافت اور اخلاق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسانیت کے خلاف حرکات کی تھیں ان کے متعلق حکم تھا کہ وہ جہاں کہیں ملیں مار ڈالے جائیں( السیرۃ النبویۃ لابن ھشام من امر الرسول بقتلہٖ).مگر پھر ان سات کو بھی معاف کر دیا گیا.انہی میں سے ایک ہندہ تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی.جس نے حضرت حمزہؓ کے ناک اور کان کٹوائے تھے اور آپ کا کلیجہ نکلوا کر چبایا تھا(البدایۃ و النھایۃ سنۃ ۳ ھـ غزوۃ احد).چونکہ ہندہ نے وہ کام کیا تھا جو لڑائی کے ساتھ ضروری نہیں.لڑائی ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہی ہیں لیکن جو کام ہندہ نے کیا تھا وہ نہایت ظالمانہ اور انسانیت کے خلاف جرم تھا اس لئے آپؐ نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے یوں بھی وہ لوگوں کو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اکساتی رہتی تھی فتح مکہ کے بعد آپ جب عورتوں سے بیعت لینے لگے تو چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا اور تمام عورتیں منہ پر پردہ ڈالے بیعت کے لئے آتی تھیں ان کے ساتھ مل کر ہندہ بھی آگئی اور وہ بھی بیعت کے الفاظ دہراتی گئی.جب آپ اس فقرہ پر پہنچے کہ ہم شرک نہیں کریں گی تو ہندہ بول اٹھی کہ یا رسول اللہ کیا اب بھی ہم شرک کریں گی.ہم ہزاروںہزار تھے اور آپ کے ماننے والے صرف چند آدمی تھے.ہم طاقتور تھے اور آپ کمزور تھے.ہمارے پاس لڑائی کا ہر قسم کا سامان موجود تھا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا.اگر ہمارے بت طاقتور ہوتے تو خواہ وہ مقابلہ نہ کرتے،غیر جانبدار رہتے تب بھی آپ جیت نہیں سکتے تھے.مگر معلوم ہو تا ہے کہ ہمارے بت بے طاقت تھے اور آپ کا خدا طاقت ور تھا اسی لئے آپ جیت گئے.آپ نے فرمایا ہندہ ہے؟ ہندہ آپ کی رشتہ دار ہی تھی اور آپؐ اس کی آواز کو پہچانتے تھے وہ تیز طبیعت تو تھی ہی فوراً بول اٹھی یا رسول اللہ بے شک آپ نے حکم دیا ہو اہے کہ جہاں میں پائی جاؤں ماری جاؤں.مگر میں اب مسلمان ہوچکی ہوں آپ مجھے مار نہیں سکتے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم پر وہ حکم نہیں چل سکتا(السیرۃ الحلبیۃ فتح مکۃ شرفھا اللہ تعالٰی).دوسرا شخص ابو جہل کا بیٹا عکرمہؓ تھا اس کے بھی مارے جانے کا حکم تھا.جب مکہ فتح ہو اتو یہ وہاں سے بھاگ گیا
Page 123
اس نے حبشہ کی طرف بھاگ جانے کی کوشش کی اور ساحل سمندر پر چلا گیا.اس کی بیوی کافی دیر سے دل سے مسلمان ہو چکی تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تو کافی دیر سے مسلمان ہوں میرا خاوند آپ کا مقابلہ کرتا رہا ہے لیکن یا رسول اللہ وہ آپ کی مخالفت اسی لئے کرتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا جوکچھ آپ کہتے ہیں وہ غلط ہے.اگر وہ اسے درست سمجھتا تو لڑتا کیوں.آپ رحیم وکریم ہیں اسے معاف کر دیں.آپ نے حکم دیا ہے کہ وہ جہاں پایا جائے مارا جائے.یا رسول اللہ وہ کسی اور ملک کو نکل جائے گا اور بر باد ہو جائے گا.کیا یہ بہتر ہے کہ آپ کا ایک رشتہ دار تباہ و برباد ہو جائے یا یہ بہتر ہے کہ وہ ہدایت پا جائے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ہدایت پا جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے.لیکن اگر وہ اپنے مذہب پر قائم رہے اور عرب میں رہے تب بھی اس کے مذہب میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا.اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اسے لے آؤں.مگر آ پ وعدہ فرمائیں کہ اسے معاف کر دیں گے.آپ نے فرمایا اگر وہ واپس آجائے گا تو اسے معاف کردیا جائے گا.وہ عکرمہؓ کی تلاش میں نکلی.عکرمہؓ ابھی حبشہ جانے کے لئے کشتی میں سوار ہی ہو رہا تھا کہ وہ وہاں پہنچی.اسے بیوی کے ساتھ بڑی محبت تھی جب دونوں آپس میں ملے تو بیوی نے کہا.اے میرے خاوند تو اتناتو سوچ کہ کیا ایک غیر عرب کی غلامی سے یہ بہتر نہیں کہ تو ایک عرب بھائی کی غلامی اختیار کر لے.پھر اتنا تو سوچ کہ تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت کی کہ حد کر دی.مگر آپؐنے فرمایا ہے کہ اگر عکرمہؓ واپس آجائے تو میں اسے معاف کر دوں گا اور اس کے مذہب میں بھی کوئی دخل نہیں دوں گا.عکرمہؓ نے کہا کیا آپؐنے ایسا کہا ہے؟بیوی نے کہا آخر تم میرے خاوند ہو میں تمہاری دشمن تو نہیں ہوں.آپؐنے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم واپس آجاؤ تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے.عکرمہؓ نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ مجھے معاف کر دیں.میں نے تو آپؐکی اتنی مخالفت کی ہے کہ اس کے بعد میری معافی کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا.بیوی نے کہا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے آئی ہوں.اگر مجھ پر یقین نہ ہو تو خود چل کر پوچھ لو.عکرمہؓ واپس لوٹا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میںحاضر ہوا.چونکہ وہ ابھی آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اس لئے آپؐکا نام ہی لیتا تھا.چنانچہ اس نے آپؐکا نام لے کر کہا میری بیوی میرے پاس گئی تھی اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپؐنے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں واپس آگیا تو آپؐمجھے معاف کردیں گے اور میرے مذہب میں بھی دخل نہیں دیں گے کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپؐنے فرمایا جو کچھ تمہاری بیوی نے تم سے کہاہے وہ درست ہے.عکرمہؓ کے لئے یہ ایک غیر معمولی بات تھی.وہ یہ خیال بھی نہیں کر
Page 124
سکتاتھا کہ آپؐاسے اپنے مذہب پر چھوڑ دیں گے اور کسی قسم کا جبر نہیں کریں گے.آپؐکا جواب سنتے ہی اس کا دل صاف ہو گیا.اس نے کہا یا رسول اللہ میں سچے دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معافی اور نیک سلوک ایک نبی کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا اس لئے میں آپؐپر ایمان لاتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عکرمہ ؓ کے ایمان لانے سے بہت خوشی ہوئی اور آپؐنے فرمایا.عکرمہ تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو آپؐکا مطلب یہ تھا کہ تمہیں اپنی جائیداد کو بچانے کی خواہش ہو تو بتا دو تمہاری خواہش قبول کر لی جائے گی.مگر کجا وہ عکرمہ ؓ جو آپؐکا دشمن تھا اور کجا اس کی یہ حالت کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے دنیا کی حاجت نہیں.میں آپؐکی بہت مخالفت کر چکا ہوں میری صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ آپؐخدا تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے.اس کے علاوہ مجھے اور کسی چیز کی حاجت نہیں(السیرۃ الحلبیۃ فتح مکۃ شـرفھا اللہ تعالٰی).یہ دوسرا شخص تھا جس کے مارے جانے کے متعلق حکم تھا.تیسرا شخص شام کی طرف بھاگ گیا تھا اور وہاں دھکے کھا رہا تھا.لوگوں نے اس سے کہا تو اپنے محسن کو چھوڑ کر کہاں بھاگا پھر تا ہے جا اور اس سے معافی مانگ.اس نے کہا میں معافی کیا مانگوں میرے متعلق تو یہ حکم ہے کہ جہاں بھی پایا جاؤں مارا جاؤں.انہوں نے کہا تم ذہین آدمی ہو بھیس بدل کر کسی نہ کسی طرح پہنچ جاؤ اور معافی مانگ لو.وہ شاعر تھا اور بڑے شاعر کا بیٹا تھا.وہ بھیس بدل کر آپؐکے دربار میںحاضر ہوا.چونکہ وہ مہاجرین کا رشتہ دار تھا اس لئے انہوں نے پہچان لیا.لیکن جنہوں نے بھی اسے دیکھا انہوں نے نگاہیں نیچی کر لیں.وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا.میں آپؐکی خدمت میں کچھ شعر لایا ہوں اجازت ہو تو سنادوں.آپؐنے اجازت مر حمت فرمائی اور اس نے وہ اشعار پڑھے جو قصیدۂ بردہ کے نام سے مشہور ہیں.عربوں کے عام دستور کے مطابق اپنی محبوبہ اور اونٹنی کا ذکر کرتے ہوئے اس نے گریز اختیار کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا.پھر کہا لوگ مجھے کہتے تھے کہ اے ابن کلثوم تو اپنے آپ کو شیر کی غار میں ڈال رہا ہے تو گیا تو مارا جائے گا لیکن میں نے کہا جانے بھی دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے والے انسان ہیں.جب اس نے یہ کہا تو انصارؓ سمجھ گئے کہ یہ شخص ان سات اشخاص میں سے ہے جن کے قتل کئے جانے کا حکم تھا.سب نے اپنی تلواریں میانوں سے نکالیں مگر انتظار میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے.کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مدّ ِنظر تھا.پھر اس نے چند اشعار کے بعد یہ شعر پڑھا.کہ
Page 125
اِنَّ الرَّسُوْلَ لَسَیْفٌ یُسْتَضَاءُ بِہٖ مُھَنَّدٌ مِّنْ سُیُوْفِ اللہِ مَسْلُوْلٌ ( السیرۃ النبویۃ لابن ہشام امر کعب بن زہیر) یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے اور وہ تلوار اللہ تعالیٰ کی تلواروں سے ایک تلوار ہے جو ہندی نمونہ کی ہے اور سونتی ہوئی ہے،پھر اس نے قرآن کریم کی تعریف کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتار ی اور اس کے اوپر ڈال دی.جس کے معنے یہ تھے کہ آپؐنے اسے معاف کر دیا.اس پر صحابہ ؓ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی.غرض اتنی خونریزی اور ایذاء دہی کے بعد جس میں آپؐکی ایک صاحبزادی حاملہ ہونے کی حالت میں فوت ہوگئیں(الاستیعاب فی معرفۃ الاصـحاب زینب بنت رسول اللہ ).آپؐکی پیاری بیوی حضرت خدیجہؓ فاقوں کی وجہ سے وفات پا گئیں آپؐکے چچا ابو طالب جو اگر چہ ایمان نہیں لائے تھے مگر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی تھی وہ بھی فاقوںکی وجہ سے فوت ہو گئے(الـسیرۃ الـحلبیۃ باب ذکر وفاۃ عـمہ ابی طالب و زوجتہ خدیـجۃ رضی اللہ عنہا).آپؐکے چچا حضرت حمزہؓ کو شہید کیا گیا اور آپ کے ناک،کان کاٹ دیئے گئے اور پیٹ پھاڑ کر جگر نکال لیا گیا.اسی طرح آپؐکو اور بھی بہت سی تکلیفیں دی گئیں.صرف سات آدمی ایسے تھے جن کے متعلق آپ نے حکم صادر فرمایا تھا کہ وہ جہاں کہیں ملیں ان کو مار ڈالا جائے.مگر ان میں سے بھی تین کی معافیاں تاریخ سے ثابت ہیں اور بعض دوسروں کا قتل تاریخ سے ثابت نہیں ہو تا.یہ پاک نمونہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا یہی وہ نمونہ تھا جس نے صحابہ کے دلوں کو پاک کیا اور انہیں بھی دنیا کا ہادی اور راہنما بنا دیا.پھر یہودیت کہتی ہے کہ تو یہودی سے سود نہ لے غیر یہودی سے سود لے سکتا ہے(استثناء باب ۲۳آیت ۱۹،۲۰) اسلام کہتا ہے کہ تو کسی سے بھی سود نہ لے.نہ مسلم سے سود لے اور نہ کسی غیر مسلم سے سود لے.اگر یہ بری چیز ہے تو پھر اپنوں اور غیروں کی تخصیص بالکل بے معنی بات ہے.پس تزکیہ عمل جو اسلام نے کیا ہے کوئی دوسرا مذہب اس قسم کے تزکیہ کی مثال پیش نہیں کر سکتا.پھر جذبات کا تزکیہ ہے.اخلاق کی تعریف جو اسلام نے کی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں کی.اسلام نے یہ کہا ہے کہ بعض مخصوص اعمال کو برا کہنا غلطی ہے.عمل اپنی ذات میں برا نہیں ہو تا بلکہ فطرتی قویٰ کا غلط استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال اسے اچھا بنا دیتاہے.مثلاً عیسائیت کہتی ہے کہ رہبانیت اختیار کرو.حالانکہ واقعہ یہ
Page 126
ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود انسان کے اندر شہوت پیدا کی ہے.اگر کوئی مذہب یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نسل نہ چلاؤ اور جو چیز خدا تعالیٰ نے خود پیدا کی ہے اس کا استعمال نہ کرو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر خدا تعالیٰ نے شہوت کا مادہ انسان کے اندر کیوں پیدا کیا جس طرح کھانے کی بھوک ہوتی ہے اسی طرح عورت اور مرد کے تعلقات کی بھی بھوک ہوتی ہے.جب بغیر کھانے کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو میاں بیوی کے تعلقات کے بغیراخلاق میں درستی کیسے پید اہو سکتی ہے.حماقت سے دوسرے مذاہب نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عورت اور مرد کا تعلق برا ہے.مگر جن قوموں نے یہ قانون جاری کیا انہی ڈاکٹروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ قوت رجولیت اور دماغی طاقت کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے جب کسی شخص کا دماغ پریشان رہنے لگتا ہے،خیالات پراگندہ ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں پرنڈرین کے ٹیکے کرواؤ.پرنڈرین کیاہے یہ اسی مادہ کا کیمیاوی ٹیکہ ہے جس پر قوت رجولیت کا انحصار ہے.ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کی رجولیت کمزور ہو جائے تو اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے.یہ گویا تصدیق ہے اسلام کی، یہ ثبوت ہے اسلام کی سچائی کا.عیسائیت کہتی ہے جذبات کو مار دینا چاہیے.رجولیت کو اس نے گناہ قرار دیا ہے اور کہا ہے شادی نہ کرو تمہارا درجہ بڑھے گا.مگر اسلام کہتا ہے جذبات کو مارنا اور شادی نہ کرنا گناہ ہے.شادی کرو،بچے پیدا کرو اور اپنی نسل کو بڑھاؤ.عیسائیت کہتی ہے ایک عورت اگر شادی نہ کرے تو یہ اس کی نیکی ہے(۱.کرنتھیوں باب ۷ آیت ۲۶تا۲۹) مگر اسلام کہتا ہے عورت اگر شادی نہ کرے تو یہ بدی ہے.بلکہ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت اگر شادی نہ کرے تو اسے مجبور کرو کہ وہ شادی کرے.مرد کے متعلق بھی اسلام یہی حکم دیتا ہے کہ وہ ضرور شادی کرے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَزَوَّجُوْا وَلُوْدًا وَّدُوْدًا(نسائی کتاب النکاح باب کراھیۃ تزویـج العقیم ) ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب بچے پیدا کرنے والی ہو اور خوب محبت کرنے والی ہو.گویا عیسائیت نے فطرت کو مارا ہے اور اسلام نے فطرت کو ابھارا ہے.اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ تزکیہ کون کرتا ہے.جو شخص شادی نہیں کرتا وہ جہاں بھی عورت کو دیکھے گا چونکہ اس کے اندر عورت کی بھوک ہو گی اس کا تزکیہ مٹ جائے گا لیکن اگر وہ شادی شدہ ہو گا تو وہ کسی غیرعورت پر نگاہِ بد نہیں ڈالے گا.کیونکہ اس کے لئے بھوک کا سوال ہی نہیں.جیسے اگر کوئی شخص بھو کاہے تو وہ جب بھی دوسروں کو کھانا کھاتے دیکھے گا تو اس کا دل للچائے گا.مگر جب اس کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو دوسروں کو کھانا کھاتے دیکھ کر اس کے اندر خواہش بھی پیدا نہیں ہو گی.اس طرح شادی شدہ آدمی کی بھوک مٹ جاتی ہے اور وہ غیر عورت کو دیکھ کر اس کی خواہش نہیں کرتا.یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت زیادہ حریص ہوتو وہ شادی شدہ ہو نے کے باوجود غیر عورتوں کو بھی بری نگاہ سے دیکھتا رہے جیسے عام طور پر جب پیٹ بھر اہو اہو تو انسان دوسروں کے کھانے کی طرف نگاہ
Page 127
نہیں اٹھاتا.لیکن بعض حریص ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو اہو تا ہے مگر پھر بھی دوسروں کو دیکھ کر ان کا جی للچانا شروع کر دیتا ہے.بہر حال عام قانون یہی ہے کہ شادی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے.یہی حکمت ہے جس کی بنا پر اسلام نے رہبانیت سے منع کیاہے.مگر عیسائیت غیر شادی شدہ ہونا افضل قرار دیتی ہے.عیسائیت کہتی ہے تو اپنے جذبات کو کچل دے اور اسلام کہتا ہے تو اپنے جذبات کا صحیح استعمال کر.کیونکہ اس کے بغیر تزکیہ پیدا نہیں ہو سکتا.اسی طرح ورثہ کے احکام ہیں.ورثہ کے متعلق دوسرے مذاہب کی یہ تعلیم ہے کہ جائیداد کا باپ مالک ہے وہ جسے چاہے اپنی جائیداد دےدے.مگر اسلام کہتا ہے ورثہ میں سب کا حق ہے.یہ درست نہیں کہ تم سب مال اور جائیداد ایک کو ہی دے دو.اسی وجہ سے اسلام نے ہر ایک کے الگ الگ حصے مقرر کئے ہیں جو ہر ایک کو ملنے ضروری ہیں جو ان حصوں کو بلا وجہ(یعنی بلا دینی وجہ)کے توڑے وہ گناہ گار ہو تا ہے.اس کے بر خلاف عیسائی ممالک میں عام طور پر جائیداد کا صرف بڑا لڑکا وارث ہو تا ہے.مگر اس صورت میں دوسرے لڑکے کیا سمجھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ بڑا نالائق تھا جس نے ہمیں اپنی جائیداد سے محروم کر دیا بلکہ یوروپ میں تو ممکن ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ اس میں ان کے باپ کاکوئی قصور نہیں حکومت نے خود ایسا قانون بنا رکھا ہے.مگر یہاں تو اس قسم کا کوئی عذر بھی نہیں ہو سکتا.بہرحال اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ سب اولاد کو اپنی جائیداد سے حصہ دو اور کسی کو اس کے جائز حق سے محروم نہ کرو.اس طرح اسلام نے نہ صرف اولاد کے حقوق کو محفوظ کر دیا بلکہ ان کے جذبات کا بھی تزکیہ کیاہے جس بچے کو ورثہ نہیں ملے گا وہ تو ماں باپ کو ساری عمر گالیاں ہی دیتا رہے گا.اس کے دل سے دعا کیسے نکلے گی.غرض اسلام نے بنی نوع انسان کو جو تعلیم دی ہے وہی تعلیم جذبات کا تزکیہ کرتی اور دل میں صحیح نیکی پیدا کرتی ہے.فکر کا تزکیہ تیسری چیز فکر کا تزکیہ ہے.فکر بھی ایک بڑی طاقت ہے جذبات وہ چیز ہیں جو انسان کے اندر وقتی طور پر ایک جوش پیدا کر دیتے ہیں.مثلاً بھوک،پیاس اور شہوت وغیرہ اور فکر میں ہم پچھلے علوم کو لے کر ان پر غور کرتے اور ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں.جذبات کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور فکر کا دماغ کے ساتھ.اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے ذریعہ وہ انسانی فکر کو بھی ساتھ ہی درست کر دیتا ہے اور اس کے لئے اس نے کئی طریق تجویز کئے ہیں سب سے پہلے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اسی وقت اس کے کانوںمیں اذان اور اقامت کہی جائے.اب بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بچہ جو بولتا نہیں جو دوسرے کی زبان کو سمجھ نہیں سکتا اس کے کان میں اذان کہی جارہی ہے.لیکن علم النفس کے ماتحت موجودہ زمانہ میں یہ حقیقت روشن ہو گئی ہے کہ بچہ کے کان
Page 128
میں جو آوازیں پڑتی ہیں وہ اس پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں.فرانس میں ایک عورت تھی وہ بعض اوقات ایسی اعلیٰ درجہ کی جرمن زبان بولتی تھی کہ سننے والے حیران رہ جاتے تھے حالانکہ وہ جرمن با لکل نہیں جانتی تھی.بعضوں نے کہناشروع کیا کہ اس پر جن سوار ہیں جو جرمن زبان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں.جب اس کا چرچا ہو اتو علم النفس کا ایک ماہر وہاں گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ عورت واقعہ میں بعض دفعہ جرمن زبان میں تقریر کرنے لگتی ہے.اس نے عورت سے مختلف سوالات کئے اور پو چھا کہ آیا اس کی والدہ کہیں کسی جرمن کے پاس نوکر تو نہیں تھی؟آخر اسے معلوم ہو اکہ اس کی والدہ ایک پادری کے ہاں ملاز م تھی جو جرمن تھا.اس وقت اس لڑکی کی عمر ڈیڑھ سال کی تھی.وہ اس پادری کو ملنے کے لئے گیا تومعلوم ہو اکہ وہ ریٹائر ہو کر وطن چلا گیا ہے.وہ اس کے وطن گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مرگیا ہے آخر وہ اس کے بیٹے کے پاس پہنچا اور اس نے دریافت کیا کہ کیا اس کے پاس اپنے باپ کی کوئی تقرریں موجود ہیںبیٹے نے گھر سے کچھ سرمن نکال کر دیئے جو جرمن زبان میں تھے.اور اس نے ان سرمنوں کا مطالعہ شروع کیا تو اسے معلوم ہوا کہ جو تقریروہ عورت کرتی ہے وہ لفظ بلفظ ان سرمنوں کی نقل ہے.پھر اسے معلوم ہوا کہ جب وہ جرمن پادری یہ تقریریں کیا کرتا تھا تو یہ لڑکی اپنی ماں کی گود میں ہوا کرتی تھی اور اگر چہ اس کی عمر اس وقت ڈیڑھ سال کی تھی مگر پھر بھی وہ تقریریں اس کے دل و دماغ پر نقش ہوتی چلی گئیں.غرض اس زمانہ میں علم النفس نے بتایا ہے کہ انسان کے دماغ میں ایسے پر دے ہیں جن پر ہر آواز منعکس ہو جاتی ہے خواہ عمرکے لحاظ سے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو.مگر اسلام نے آ ج سے تیرہ سو سال پہلے جبکہ دنیا موجودہ علوم سے با لکل نا آشنا تھی اس کی طرف توجہ دلائی اور پہلے دن بچہ کے کان میں اذان دینے کا حکم دے کر بتایا کہ بچہ کی تربیت اس کی پیدائش کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے.تمہارا فرض ہے کہ تم اس کے کان میں ہمیشہ نیک باتیں ڈالو.اگر پہلے دن اس کے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے تو دوسرے دن اس کے کان میں جو آواز پڑے وہ پہلے دن کی آواز سے اچھی ہو اور تیسرے دن جو آواز پڑے وہ دوسرے دن کی آواز سے اچھی ہو.گویا اسلامی نقطہ نگاہ سے فکرکی پاکیزگی ایسی ہی چیز ہے کہ پہلے دن سے ہی بچے کے کان میں نیک باتیں ڈالنا خواہ ان کو سمجھنے کی اہلیت اس میں بعد میں پیدا ہو ہر مومن کا فرض ہے تاکہ بڑے ہو کر بھی اسے فکر صحیح کی عادت پڑے.حقیقت یہ ہے کہ غلط فکر انسان کے عقائد کو بھی خراب کر دیتا ہے.مثلاً اس زمانہ میں بد قسمتی سے مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور دوسرے لوگوں کا مال لوٹ کر انہیں دے دیں گے.اس عقیدہ کی وجہ سے تمام قوم میں خطرناک سستی اور غفلت پیدا ہو گئی ہے.اگر ان کا فکر درست ہو تا تو وہ سمجھتے کہ بغیر قربانی کے دنیا پر فتح حاصل نہیں ہو سکتی اور
Page 129
آج تک کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں گذری جس نے تکالیف برداشت کئے بغیر کامیابی حاصل کی ہو.سب سے بڑے تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہوتے ہیں مگر انہیں بھی قربانیاں کرنی پڑیں.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے.مہدی ہو یا عیسیٰ آپ کا غلام ہی ہو گا.مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں کرنی پڑیں تو اس کو کیوں نہ کرنی پڑیں گی.پس فکر کی خرابی کا عقائد کی درستی اور صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اسی لئے اسلام نے فکر کی درستی پر خاص طور پر زور دیاہے.پھر حیات مسیح کے عقیدہ میں ہی نہیں بلکہ کئی اور عقائد میں بھی مسلمانوں کے فکر کی خرابی کا دخل ہے.مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو تلوار کے زور سے تمام کفار کو مسلمان بنائے گا اور جو نہیں مانیں گے انہیں موت کے گھاٹ اتار دے گا.وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جبر کے نتیجہ میں دوسرا شخص زبان سے تو سچائی کا اقرار کر لے گا مگر اس کے دماغ پر کیسے اثر پڑے گا اور اگر وہ دل سے اقرار نہیں کرے گا تو اس کے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا وہ تو منافق بن جائے گا.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے رسول تیرے پاس منافق آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے مگر منافق جھوٹے ہیں.اگر جبری طور پر کسی کو منوا لینا درست ہو تا تو پھر منافق کہہ تو رہے تھے کہ تُو سچا نبی ہے.آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ بھی اب کہنے لگے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں مگر باوجود اس کے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا صرف منہ سے گواہی دے دینا کافی نہیں.ان کے دل اقرار نہیں کرتے اس لئے وہ جھوٹے ہیں.اگر لٹھ سے تم کسی کو منوا لو گے تو وہ ایمان تو لے آئے گا لیکن اس کے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہو گا اور اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہو گا.مثلاً تم کہتے ہو خدا تعالیٰ ایک ہے اور وہ تین خدا مانتا ہے.اگر تم اسے لٹھ سے ایک خدا منواؤ گے تو وہ منہ سے تو کہہ دے گا کہ خدا ایک ہے مگر وہ دل سے یہی کہے گا کہ خدا تین ہیں.گویا جبر سے اس کے اندر ایمان پیدا کرنے کی بجائے ہم منافقت پیدا کر دیں گے اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہو گی.جب تک وہ اپنے عقائد پر قائم تھا اور اس کا ظاہر و باطن ایک تھا خواہ اس کا عقیدہ غلط ہی کیوں نہ تھا اس بات کا امکان تھا کہ اسے سمجھا کرسیدھے راستہ پر لایا جائے.لیکن اگر ہم جبر کر کے اسے منواتے ہیں تو گویا ہم اسے کہتے ہیں کہ تم منہ سے کچھ کہو اور دل میں کچھ رکھو اس طرح منافقت میں ہم اسے پکا کر دیتے ہیں.جب تک وہ سچ بولتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ اگر ہم دلیل دیں گے تو وہ مان جائے گا مگر ہم نے اسے منافقت کی عادت ڈال کر بے ایمانی میں اور بھی پختہ کردیا.پس فکر کی درستی نہایت ضروری چیز ہے اور یہ اسلام نے ہی کی ہے کسی اور مذہب نے ایسی تعلیم نہیں دی جو فکر
Page 130
کی اصلاح کرنے والی ہو.غرض تزکیہ اسلام کی اتباع کالازمی نتیجہ ہے اور یہ چیز کسی اور مذہب میںنہیں پائی جاتی پس ثابت ہو اکہ تزکیہ صرف اسلام ہی کر سکتا ہے.اب تک تو اصولی طور پر میں نے تزکیہ قلوب کے متعلق اسلامی تعلیم کو پیش کیاہے.اب ہم عملًا دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام تزکیہ کرتاہے.کیا اس کے بالمقابل دوسرے مذاہب نے سابق زمانوں میں ویسا تزکیہ کیا ہے یا کیا اب وہ مذاہب تزکیہ کر سکتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے پہلے مخاطب عرب تھے اور آپ پر ایمان لانے والوں میں کچھ عورتیں کچھ بچے اور کچھ مرد تھے.ان مردوں میں سے کچھ غلام تھے جن کی کوئی پوزیشن اور حیثیت نہیں تھی،ان کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی شہری حقوق انہیں حاصل نہیں تھے،آقا ان کو مار ڈالتے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ اپنے آقاؤں کی ملکیت سمجھے جاتے تھے.ا س وقت کوئی قانون نہیں تھا جو ان کی حفاظت کر سکتا.جب بعض غلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو تپتی ریتوں پر انہیں لٹایا جاتا، پتھروں پر گھسیٹا جاتا یہاں تک کہ ان کے جسم چھل جاتے اور وہ شدید زخمی ہو جاتے.جب کچھ عرصہ کے بعد ان کے زخم مندمل ہو جاتے تو پھر دوبارہ ان کو پتھروں پر گھسیٹتے اور یہ سلوک ان سے متواتر جاری رکھا جاتا.یہاں تک کہ ان میں سے بعض کی کھال بھینسے کی کھال کی مانند ہو گئی.حضرت بلال ؓ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا آقا آپ کو پیٹھ کے بل لٹا کر جوتیوں سمیت آپ کے سینہ پر کودا کرتا اور کہتا کہو خدا تعالیٰ کے سوا اور بھی بہت سے خدا ہیں اور اس پر بار بار اصرار کرتا حضرت بلالؓ حبشی تھے اور اس وجہ سے عربی اچھی طرح نہیں بول سکتے تھے.جب کفار زیادہ ظلم کرتے اور اصرار کرتے تو آپ کہتے اَسْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ جب آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مؤذن مقرر کیا اور آپ اَسْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ کہتے تو نوجوان ہنس پڑتے.انہوں نے وہ نظارے نہیں دیکھے تھے جب کفار ان کے سینہ پر کودا کرتے تھے اور اصرار کرتے تھے کہ کہو خدا کے سوا اور بھی معبود ہیں.مگر آپ کہتے اَسْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بعض نوجوانوں کو ہنستے دیکھا تو آپؐنے فرمایا خدا تعالیٰ کو بلالؓ کا اَسْھَدُ کہنا اتنا پیارا ہے کہ اس کے مقابلہ میں تمہارا اَشْھَدُ کہنا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا.تمہیں کیا معلوم کہ کن حالات میں یہ اَسْھَدُ کہا کرتا تھا.اس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا، نہ بھائی تھا، نہ بیٹا تھا، نہ قبیلہ تھا اور نہ کوئی خیر خواہ تھا جو اس کی مدد کر تا.کفار اس کے سینے پر ناچتے تھے اسے گلیوں میں گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے کہو خدا ایک نہیں بلکہ بہت سے معبود ہیں.مگر یہ کہتا اَسْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ میں یہی گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں.دیکھو کتنا شاندار ایمان ہے
Page 131
جس کا نمونہ حضرت بلال ؓ نے دکھایا اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنھوں نے وہ نظارہ دیکھا ہے یا جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے اذان دینی چھوڑ دی تھی کیونکہ آپ کی اذان کا حقیقی قدر دان دنیا میں نہیں رہا تھاایک عرصہ دراز کے بعد جب نئے لوگ آئے تو انہوں نے اصرار کیا کہ بلالؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اذان دیا کرتا تھا اسے کہوکہ وہ اذان دے تاکہ ہم بھی اس کی آواز سن لیں.صحابہؓ آپ کے پیچھے پڑگئے.آپ انکار کرتے رہے لیکن جب صحابہؓ نے زیادہ زور دیا تو آپ مان گئے اور آپ نے اذان دی.ان کا اذان دینا تھاکہ صحابہ ؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آگیا اور وہ اس طرح بلبلاکر روئے جس طرح کوئی ماتم بر پا ہوجاتا ہے اور ان کی گھگی بندھ گئی.حضرت بلا ل ؓ نے اذان ختم کی تو وہ بےہوش ہو گئے اور پھر اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا(الاستیعاب بلال رضی اللہ عنہ بن رباح).دیکھو کتنی پاکیزگی صحابہؓ کے اندر پائی جاتی تھی اور کتنی محبت انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باجود سے تھی.اور کون سا نبی ہے جس کے متبعین میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نظر آسکے.مگر یہاں تو اس قسم کی ہزاروں مثالیں پائی جاتی ہیں.ابو بکرؓ جیسا انسان جس کا سارا مکہ ممنون احسان تھا وہ جو کچھ کماتے تھے غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیتے تھے آپ ایک دفعہ مکہ کو چھوڑ کر جارہے تھے کہ ایک رئیس آپ سے راستہ میں ملا اور اس نے پو چھا ابو بکر تم کہاں جارہے ہو آپ نے فرما یا اس شہر میں اب میرے لئے امن نہیں میں اب کہیں اور جارہا ہوں.اس رئیس نے کہا تمہارے جیسا نیک آدمی اگر شہر سے نکل گیا تو شہر بر باد ہو جائے گا.میں تمہیں پناہ دیتا ہوں تم شہر چھوڑ کر نہ جاؤ.آپ اس رئیس کی پناہ میں واپس آگئے آ پ جب صبح کو اٹھتے اور قرآن پڑھتے تو عورتیں اور بچے دیوار کے ساتھ کان لگا لگا کر قرآن سنتے.کیونکہ آ پ کی آواز میں بڑی رقت،سوز اور درد تھا اور قرآن کریم چونکہ عربی میں تھا ہر عورت،مرد،بچہ اس کے معنے سمجھتا تھا اور سننے والے اس سے متاثر ہوتے تھے.جب یہ بات پھیلی تومکہ میں شور پڑ گیا کہ اس طرح تو سب لوگ بے دین ہو جائیں گے.آخر لوگ اس رئیس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم نے اس کو پناہ میں کیوں لے رکھا ہے.اس رئیس نے آکر آپ سے کہا کہ آپ اس طرح قرآن نہ پڑھا کریں مکہ کے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں.حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا پھر اپنی پناہ تم واپس لے لو میں تو اس سے باز نہیں آسکتا.چنانچہ اس رئیس نے اپنی پناہ واپس لے لی(بخاری کتاب مناقب الانصار باب ھجرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینۃ) یہ آپ کے تقویٰ اور طہارت کا کتنا زبر دست ثبوت ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ شدید دشمن تھے اور آپ کو گالیاں بھی دیا کرتے تھے.لیکن ابو بکرؓ کی پاکیزگی کے وہ اتنے قائل تھے کہ اس رئیس نے کہا آپ کے نکل
Page 132
جانے سے شہر بر باد ہو جائے گاحضرت عمرؓ کی بھی لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے اور آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے.دشمن کی زبان سے ان کی تعریف کا نکلنا بتاتا ہے کہ ان کی پاکیزگی کمال کو پہنچ گئی تھی حضرت علیؓ کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہیں بہت نیک سمجھا جاتا تھا اسی طرح باقی صحابہ کے متعلق لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں.پھر صحابہ ؓ نے نیکی کا وہ نمونہ دکھا یا جس کی مثال دنیاکی کسی اور قوم میں نہیں ملتی.جنگ بدر،حنین اور احزاب میں جو صحابہ ؓ نے قربانیاں کیں ان کی مثال کسی اور قوم میں کہاں مل سکتی ہے.احزاب میں مسلمان صرف سات سو کی تعداد میں تھے اور کفار کا لشکر پندرہ ہزار کے قریب تھا میور جیسا دشمن اسلام لکھتا ہے کہ حیرت آتی ہے کہ تھوڑے سے آدمی اتنے بڑے لشکر کو کس طرح روک رہے تھے پھر وہ لکھتا ہے کہ اصل میں اتنے بڑے لشکر کو اگر کسی نے روکا تو اس دیوانہ وار محبت نے جو صحابہؓ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی.وہ خود لکھتا ہے کہ با ر ہا ایسا ہوا کہ دشمن خندق پھاند کر آگے بڑھ آیا اور قریب تھا کہ وہ مدینہ کو تباہ کر دیتا مگر جب وہ ہزاروں کا لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی طرف رخ کرتا تو یوں معلوم ہو تا تھا کہ صحابہؓ دیوانے ہو گئے ہیں.وہ آپؐکے خیمہ کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ کے گرد گرنا شروع کرتے اور اس بے جگری سے لڑتے کہ ہزاروں کے لشکر کو تتر بتر کر دیتے اور پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ متواتر یہ نظارہ نظر آتا ہے اور جس طرف بھی نگاہ پڑتی صحابہؓ پر وانوں کی طرح قربان ہوتے نظر آتے تھے.(لائف آف محمد صفحہ ۳۲۲،۳۲۳) ایک دفعہ د وصحابہؓ کو کفار دھوکا سے لے گئے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ انہیں بیچ دیا جن کے باپ جنگوں میں مارے گئے تھے جب ان میں سے ایک کو کفار مارنے لگے تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تا کہ اس نظارہ کو دیکھیں.ابوسفیان بھی بلا یا گیا جب اس صحابی کی گردن لکڑی پر رکھی گئی اور وہ اسے مارنے لگے تو اس نے کہا ذرا مجھے نماز پڑھ لینے دو.انہوں نے کہا اچھا تم نماز پڑھ لو.جب اس صحابی ؓ نے نماز پڑھ لی تو اس نے کفار سے مخاطب ہو کر کہا.میں نے لمبی نماز پڑھنی تھی مگر اس لئے جلدی جلدی پڑھ لی ہے تا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈرتا ہوںپھر اس صحابی ؓ نے دو شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستہ میں موت آجائے تو پھر اس بات کا سوال ہی کیا ہے کہ سر کٹ کر دائیں طرف گرتا ہے یا بائیں طرف گرتا ہے جو حالت بھی ہو اس میں خوش رہنا چاہیے.ایک دوسرے صحابی سے جو اسی طرح مکہ والوں کے ہاتھ میں آگیا تھا کفار نے پو چھا کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم تو اس وقت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور تمہاری جگہ اس وقت محمد(صلی اللہ علیہ وسلم) ہماری قید میں ہوتے.اس صحابی ؓ نے کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ میں مدینہ میں آرام سے بیٹھا ہو اہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جگہ ہوں خدا کی قسم میرا دل تو
Page 133
یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں آرام سے گھر میں بیٹھا ہو اہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے( السیرۃ النبویۃ لابن ھشام ذکر یوم الرجیع فی سنۃ ثلاث) یہ آپ کے تزکیہ کا کتناشاندار ثبوت ہے کہ صحابہ ؓکے اندر آپ کی ایسی محبت قائم ہو گئی جس کی مثال دنیا کے پر دہ پر اور کہیں نظر نہیں آسکتی.ہمارے ہاں مرد جنگ پر جاتے ہیں تو عورتیں روتی ہیں مگر اس وقت عورتیں اپنے خاوندوں کو مجبور کرتی تھیں کہ وہ جہاد کے لئے باہر جائیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لئے تشریف لے گئے تو ایک صحابی جو کئی دنوں سے باہر کسی سفر پر گئے ہوئے تھے گھر آئے.خاوند کو بیوی سے محبت ہوتی ہے آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی چاہا کہ بیوی سے پیار کریں لیکن جب آگے بڑھے تو بیوی نے آپ کو زور سے دھکہ دے کر پیچھے ہٹا دیا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگ کے لئے تشریف لے گئے ہیں اور تمہیں بیوی سے پیار سوجھ رہا ہے وہ صحابی اسی وقت پیچھے ہٹ گئے.دروازہ کھولا اور جنگ کے لئے چلے گئے.کتنا بڑ اعشق ہے جو صحابہؓ کے دلوں میں پا یا جاتا تھا اس کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو.جب انہیں مقابلہ کرنا پڑاتو اس نے کہہ دیا اِذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ (المائدۃ:۲۵) جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑتے پھرو.ہم تو یہیں بیٹھے ہیں.شہر فتح کرکے دے دو گے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے.پھر مسیح علیہ السلام کے حواریوں کو دیکھو جب حضرت مسیح علیہ السلام کو روما کے سپاہی پکڑ کر لے گئے تو آپ کے سب سے بڑے حواری جو بعد میں آپ کے خلیفہ بھی ہوئے یعنی پطرس وہ آپ کے پیچھے پیچھے جارہے تھے کہ کسی نے کہا یہ بھی اس کا حواری ہے اسے بھی قید کر لو.تمام ہجوم ادھر آگیا اور پطرس کو پکڑ لیا اس نے کہا میں تو اس پر لعنت بھیجتا ہوں میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے.پھر وہ آگے چلے تو پھر کسی نے کہا کہ یہ بھی اس کا حواری ہے اسے بھی پکڑ لو.پطرس نے پھر دوسری دفعہ آپ پر لعنت کی جس پر اسے چھوڑ دیا گیا مگر پھر لوگوں کی توجہ اس کی طرف پھری اور انہوں نے پھر پکڑلیا.پطرس نے پھر مسیح علیہ السلام پر لعنت کی جب وہ تیسری بار لعنت کر چکا تو اس وقت مرغ نے اذان دے دی(متی باب ۲۶ آیت ۶۹تا ۷۵).یہ در اصل حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کا ظہور تھا.پطرس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا.اس پر حضرت مسیح نے کہا پطرس تُو تو یہ کہتا ہے اور میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو آج رات مرغ کے اذان دینے سے پہلے تین دفعہ مجھ پر لعنت کرے گا.چنانچہ ادھر اس نے تین دفعہ لعنت کی اور ادھر مرغ نے اذان دے دی اور آپ کی پیشگوئی پوری ہو گئی.اب کجا یہ نمونہ اور کجا صحابہ کی فدائیت دونوں میں کوئی بھی تو نسبت نہیں.
Page 134
پھر آپ کی زندگی کے بعد بھی ایسے نظارے نظر آتے ہیں جو صحابہؓ کے بلند کیریکٹر کے شاہد ہیں.جب یروشلم فتح ہوا تو ایک وقت ایسا آیا جبکہ مسلمان اسے اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکے اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا.یہ حضرت عمر ؓ کا زمانہ تھا یروشلم عیسائیوں کا مر کز تھا اور عیسائیوں سے ہی آباد تھا.مسلمانوں نے انہیں بلا کر ان کا ٹیکس واپس کر دیا اور کہا اب ہم واپس جا رہے ہیں اور چونکہ ہم نے یہ ٹیکس تمہاری حفاظت کے لئے لیا تھا اس لئے ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم تمہارا روپیہ اپنے پاس رکھیں.تاریخ میں آتا ہے کہ مسلمان جب یروشلم سے باہر نکلے تو عیسائی عورتیں اور بچے دو تین میل تک ان کے پیچھے پیچھے آئے تا کہ انہیں روک لیں اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ خدا مسلمانوں کو پھر واپس لائے( الـخراج لابی یوسف فصل فی الکنائس والصلبان) گویا وہ ایک غیر حکومت کا تسلط چاہتے تھے اس لئے کہ ان کے اندر نیکی پائی جاتی تھی اس لئے کہ ان کے اندر انصاف پایا جاتا تھا.دنیوی حکومتوں کے لشکر جب کسی جگہ سے لوٹتے ہیں تو وہ شہر کو لوٹ لیتے ہیں مگر یہاں مسلمان فوج کے کمانڈر نے وہ روپیہ بھی شہر والوں کو واپس دے دیا جو ان سے بطور ٹیکس وصول کیا گیا تھا.یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ کا کتنا زبر دست ثبوت ہے.اسی طرح ایک دفعہ کفار نے دھوکہ سے ایک حبشی مسلمان سے معاہدہ کر لیا اور انہوں نے قلعہ کے دروازے کھول دیئے جب لشکر آگے بڑھا تو انہوں نے کہا ہمارا تم سے معاہدہ ہو چکا ہے.کمانڈر نے کہا مجھے تو پتہ نہیں.انہوں نے کہا ہم نے ایک حبشی سے معاہدہ کر لیا تھا.اسلامی لشکر کے کمانڈر نے کہا کمانڈر تو میں ہوں اسے معاہدہ کا کیا اختیار تھا.کفار نے کہا ہم نہیں جانتے ہم اس سے معاہدہ کر چکے ہیں.آخر حضرت عمر ؓ کو لکھا گیا کہ ایسا واقعہ ہو اہے اب کیا کیا جائے.آپ نے جواب دیا میں یہ پسند نہیں کر تا کہ کسی مسلمان کی زبان جھوٹی ہو.اس دفعہ تم اس معاہدہ کو پورا کرو لیکن آئندہ کے لئے احتیاط رکھو.(تاریخ الطبری ذكر مصالـحه المسلمين اهل جندى سابور) پھر یہ واقعات صرف زمانہ صحابہ ؓ تک ہی نہیں تھے بلکہ بعد میں بھی مسلمانوں نے اس تزکیہ کی بڑی بڑی شاندار مثالیں پیش کیں ہیں.گبن جو یوروپ کا ایک مشہور مؤرخ ہے وہ مسلمانوں کے ایک بادشاہ مالک ارسلان کی نسبت لکھتا ہے کہ جب اس کا باپ مر گیا تو اس کی عمر۱۸ سال کی تھی.باپ کے مرنے کے بعد مالک کے چچا اور بھائی نے بغاوت کر دی اور کہا کہ بادشاہت کا حق ہمارا ہے.علامہ نظام الدین طوسی جو اس کے وزیر اعظم تھے اور جو شیعہ عقائد کے تھے انہوں نے مالک سے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ رضا کی قبر پر تشریف لے چلیں اور دعا کریں خدا تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے گا.مالک نے یہ بات مان لی اور وہ دونوں موسیٰ رضا کی قبر پر گئے اور دعا کے لئے جھکے.نظام الدین طوسی جب سجدہ سے اٹھا اور دعا سے فارغ ہو اتو اپنے اخلاص کو ظاہر کرنے کے لئے اس نے کہا بادشاہ سلامت! میں
Page 136
تَدَّعُوْنَ (حٰمٓ السجدۃ:۳۱،۳۲) وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کو رب کہنے کی وجہ سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے ان کو تکالیف دی جاتی ہیں،ان کو قسم قسم کی ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں اور وہ انہیں بر داشت کر کے استقامت اور صبر کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہیں.ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو تے ہیں جو انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئندہ جو کچھ ہو نے والا ہے اس سے ڈرو نہیں اور پیچھے جو کچھ نقصان ہو چکا ہے اس پر غم نہ کرو اور اس جنت کے ملنے پر خوشی مناؤ جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیاہے.یہاں سوال پیداہو تا تھا کہ وہ جنت کہاں ہو گی اس جہان میں یا اگلے جہان میں یا دونوں جہانوں میں؟ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جنت صرف اگلے جہان میں نہیں ہو گی جیسا کہ غیر احمدیوں کا عقیدہ ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے فرشتے مومنوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم کو جنت ملے گی اور ہم اس دنیا میں بھی تمہاری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہو ں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں تمہاری تائید کا حکم دیا ہے.اس سے ظاہر ہے کہ جنت کا لفظ اس دنیا کے لئے بھی بولا گیا ہے اور اگلے جہان کے لئے بھی.یہ ہے وہ سلوک جو امت محمدیہ کے کامل افراد کے ساتھ ہو تا ہے اور ہو تا رہے گا صرف اگلے جہان میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ہو گا اور اگلے جہان میں بھی ہو گا.ایک اور مقام پر اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ (الرحـمٰن:۴۷) وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان کو دو جنتیں ملیں گی.ایک اس جہان میں اور ایک اگلے جہان میں.یہ محض ڈھکوسلہ ہے کہ جنت صرف اگلے جہان میں ملتی ہے.خدا تعالیٰ صاف طور پر فرما تا ہے کہ مومن کواگلے جہان میں جنت ملے گی اور اس جہان میں بھی جنت ملے گی.اگر جنت صرف اگلے جہان میں ہی ہو تو ہم کسی غیر مذہب والے کو کیا ثبوت دے سکتے ہیں.وہ کہہ دے گا کہ میں تو اگلے جہان کو مانتا ہی نہیں.جب تک ہم خدا تعالیٰ کا وہ سلوک اور تائید جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے اسے نہ دکھائیں وہ اگلے جہان کے وعدوں پر اعتبار نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم اسے اپنے ساتھ خدا تعالیٰ کا امتیازی سلوک اور اس کی وہ تائیدات جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہیں دکھا دیں تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ اگلے جہان میں بھی خدا تعالیٰ کا سلوک ہمارے ساتھ ایسا ہی ہو گا اور اس کی تائید ہمارے شامل حال ہو گی.یہ ایک عظیم الشان وعدہ ہے جومومنوں سے کیا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ کمزور ہوں گے باوجود اس کے کہ دنیامیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو گی پھر بھی جو کچھ وہ چاہیں گے وہی ہو گا اور انہی کی بات دنیا میں پھیلے گی اور ان کے مخالف بالکل کمزور اور ذلیل ہو جائیں گے.قرب الٰہی کے حصول کا یہ دعویٰ اور اس کی یہ نمایاں علامات جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں نہیں پائی جاتیں.جو ثبوت ہے اس بات کا کہ حقیقی تزکیہ
Page 137
صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں ہی پا یا جاتا ہے.پھر تزکیہ کے لئے ضروری ہے کہ تزکیہ کرنے والا خود مزکّٰی ہو لکھا پڑھا آدمی ہی دوسرے کو پڑھا سکتا ہے اس لئے جو شخص دوسرے کا تزکیہ کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی تزکیہ یافتہ ہو.اس لحاظ سے بھی جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تزکیہ کے بارہ میں بھی کوثر عطا فرمایا ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت کے ماتحت آپ کو ہر حالت میں سے گذارا تاکہ آپ کے مزکّٰی ہونے کا ثبوت اہل دنیا کو مل سکے.(۱)اس تزکیہ کا ایک ثبوت تو آپ کی عمر کے ابتدائی زمانہ میں ہی نظر آتا ہے اوروہ اس طرح کہ آپ پچیس سال تک کنوارے رہے اور اس عرصہ میں آپ نے ایسی غیر معمولی عفت کا ثبوت دیاکہ دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ آپ کا کسی عورت کے ساتھ نا جائز تعلق تو کیا معمولی خلا ملا ہی ہو.یا آپ نے کسی عورت سے ایسی باتیں کیں ہوں جن سے آپ کی بے تکلفی ثابت ہو آپ نے عمر کا مضبوط ترین حصہ غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں گذار دیا مگر آپ پر کوئی الزام نہیں آیا اس کے مقابلہ میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے جنہیں بعض کے نزدیک خدا تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور بعض کے نزدیک آپ صلیب پر فوت ہو کر دوبارہ زندہ ہوئے اور آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو ان کے متعلق خود انجیل کہتی ہے کہ ان کے اردگرد ہمیشہ عورتیں رہتی تھیں وہ آپ کو مالش کرتی تھیں آپ کا سر جھستی تھیں اور آپ کو خوشبو ملاکرتی تھیں(لوقاباب ۷ آیت ۳۸) اب کجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچیس سالہ زندگی کہ اس پر کوئی دشمن بھی الزام نہیں لگا سکا اور کجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جس کے متعلق خود انجیل ایسی باتیں کہتی ہے جو آپ کی شان کو بٹہ لگانے والی ہیں.اس میںکوئی شبہ نہیں کہ ہم اعتقاداً یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی پاک تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ سے زیادہ پاک تھی اور صرف پاک ہونا اور چیز ہے اور زیادہ پاک ہونا اور چیز ہے.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاکیزگی حاصل تھی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوثر عطا ہو اتھا یعنی آپ کو پاکیزگی کی انتہا ملی تھی اور ان دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے.(۲)پھر آپ غریب تھے لیکن غربت کے باوجود آپ نے غیر معمولی استغنا کا ثبوت دیا آپ اس خاندان میں سے تھے جو خانہ کعبہ کا محافظ تھا مگر کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتاکہ آپ نے کسی سے کبھی کوئی چیز مانگی ہو یا اس کے مانگنے یا حاصل کرنے کی خواہش ہی کی ہو.آپ کے والد جب وفات پا گئے تو پہلے آپ کے دادا عبدالمطلب نے آپ
Page 138
کو پرورش میں لے لیا.پھر ان کے فوت ہو جانے کے بعد آپ اپنے چچا کے پاس رہے لیکن کہیں سے بھی یہ ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی کسی سے سوال کیا ہو.ابو طالب کو اپنے باپ کی وصیت اور آپ کی ذاتی نیکی کی وجہ سے آپ سے بے حد محبت تھی اور وہ آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ عزیز رکھتے تھے آپ کی عمر اس وقت آٹھ نو سال کی تھی.بعض دفعہ جب ابو طالب گھر آتے اور دیکھتے کہ ان کی بیوی اپنے بچوں میں کوئی چیز بانٹ رہی ہے اور آپ ایک طرف کوہ ِوقار بنے بیٹھے ہیں تو ان کی محبت جوش میں آجاتی اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لیتے اور اپنی بیوی سے کہتے میرے بچے کو تم نے نہیں دیا میرے بچے کو تم نے نہیں دیا.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے تھے یہ تو آپ کی بچپن کی حالت کا نقشہ ہے آپ جب بڑے ہوئے تو یہ آپ کے استغنا کا ہی نتیجہ تھا کہ سارے ملک نے آپ کا نام امین رکھا ہو اتھا یعنی لالچ آپ میں با لکل نہیں اور یہ کہ آپ پورے طور پر دوسرے کی امانت اس کے سپرد کر دیتے ہیں آپ کا نام صدوق بھی رکھا گیا تھا( بـخاری کتاب التفسیر تفسیر سورۃ الشعراء والسیرۃ النبویۃ لابن ھشام حدیث بنیان الکعبۃ) یعنی آپ راست باز بھی ہیں اور یہ ثبوت ہے آپ کے تزکیہ یافتہ ہو نے کا جو آپؐکی زندگی میں نظر آتا ہے.(۳)پھر آپ کے پاکیزہ اخلاق کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے شادی کی تو ایسی عورت سے جس کی عمر چالیس سال کی تھی اور ایسی بھر پور جوانی میں کی جب کہ آپ پچیس سال کے تھے اور پھر اس تعلق کو نہایت خوبی کے ساتھ نبھا یا.دشمن کہہ سکتا ہے کہ آپ نے دولت کے لالچ سے ایسا کیا مگر واقعات بتاتے ہیں کہ دولت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا.حضرت خدیجہ ؓ نے محض آپؐکی نیکی اور دیانت دیکھ کر آپ سے شادی کی.در حقیقت اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ تجارت کا قافلہ جب شام کو جاتا تو امراء اپنے نمائندے اس میں بھیجتے تھے جو ان کی طرف سے تجارت کیا کرتے تھے.حضرت خدیجہ ؓ چونکہ ایک مالدار شخص کی بیوہ تھیں اور خود بھی مالدار تھیں وہ بھی اس قافلہ میں اپنے آدمی بھجوایا کرتی تھیں.جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شہرت سنی تو آپ کو اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کر کے تجارت کے لئے بھیج دیا.اس تجارت میں حضرت خدیجہ ؓ کو اتنانفع ہو اکہ اس سے قبل اتنا نفع کبھی نہیں ہو اتھا.انہوں نے آ پ کی واپسی پر اپنے غلاموں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس شخص کی برکت ہے باقی لوگ جاتے ہیں تو نفع والا سودا دیکھ کر اپنی تجارت کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں کیا جہاں نفع کی صورت ہوتی وہاں آپ کا مال لگا دیتے اور پھر پہلے تو ہم کھا پی بھی لیتے تھے اس دفعہ انہوں نے ہمیں ناجائز طور پر کھانے بھی نہیں دیا اور خود بھی نہیں کھایا.یہ کہتے تھے کہ مال سب مالک کا ہے اور جتنا خرچ تمہارے لئے
Page 139
مقررہے اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا.اس کا قدرتی طور پر یہ نتیجہ ہو اکہ نفع زیادہ آیا ہے اس چیز کا حضرت خدیجہ ؓ کے دل پر خاص طور پر اثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس نوجوان سے شادی کر لوں.آپ نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا انہوں نے بھی کہا کہ تعریف تو اس کی بہت سنی ہے آپ شادی کر لیں تو کوئی حرج نہیں.اس کے بعد آپ نے اپنی ایک سہیلی ابو طالب کے پاس بھیجی اس نے آپ سے جا کر کہا کہ اگر خدیجہؓ کے ساتھ آپ کے بھتیجے کی شادی ہوجائے تو کیا آپ راضی ہیں.ابو طالب نے کہا کہ خدیجہ ؓ سے میرے بھتیجے کی شادی ہو جائے یہ ناممکن بات ہے وہ مال دار عورت ہے اور میرے بھتیجے کے پاس کچھ بھی نہیں بھلا اس سے خدیجہ ؓ کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ خدیجہ ؓ کی سہیلی نے کہا اگر شادی ہوجائے تو پھر؟ابو طالب نے کہا اگر ہوجائے تو بڑی اچھی بات ہے پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پا س گئی اور کہا آپ کی اگر خدیجہ ؓ سے شادی ہو جائے تو کیا آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو مال دار عورت ہے اور میں ایک غریب آدمی ہوں میرا اور اس کا کیا جوڑ ہے.حضرت خدیجہ ؓ کی سہیلی نے کہا اگر وہ خود شادی کی خواہش کرے تو کیا آپ اس سے شادی کرنے کے لئے تیار ہیں؟آپ نے فرمایا اگر اسے خود خواہش ہو تو مجھے منظور ہے.چنانچہ اس کے بعد رشتہ داروں میں گفتگو ہوئی اور آپ کا نکاح ہو گیا گویا یہ نکاح محض آپ کی نیکی کا نتیجہ تھا اس لئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ نے مال کی وجہ سے خدیجہ ؓ سے شادی کر لی تھی.پھر باوجودیکہ آپ کی عمر اور حضرت خدیجہ ؓ کی عمر میں پندرہ سال کا فرق تھا آپ پچیس سال کے تھے اور حضرت خدیجہ ؓ چالیس سال کی اورباوجودیکہ عورت قریباً پچاس سال کے بعد شادی کی عمر سے نکل جاتی ہے یعنی صرف دس سال کے بعد آپ پینتیس سال کے ہو گئے اور حضرت خدیجہ ؓ پچاس سال کی ہو گئیں جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ نے ایسی غیر معمولی وفا کا ثبوت دیاا ور اس تعلق کو ایسی خوبی سے نبھا یا کہ دنیا کے پردے پر بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ایسی وفا کرتے ہیں.حضرت خدیجہؓ نے ہجرت سے اڑھائی تین سال قبل وفات پائی ہے گویا حضرت خدیجہ ؓ کی عمر وفات کے وقت ۶۵ سال کی تھی اور اس عمر میں عورت با لکل بڑھیاہو جاتی ہے اور اس میں کوئی جسمانی دلکشی باقی نہیں رہتی کہ اس کا خاوند اسے یاد کرے.پھر اس کے بعد آپ کی کئی شادیاں بھی ہوئیں اور جوان لڑکیوں سے ہوئیں ان میں سے بعض ایسی بھی تھیں جو اپنے گرد و پیش میں حسن کا شہرہ رکھتی تھیں مگر آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ ہمیشہ انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ حضرت خدیجہ ؓ کا نام لیتے اور فرماتے خدیجہؓ کی یہ بات ہے خدیجہ ؓ کی وہ بات ہے( السیرۃ النبویۃ لابن ھشام حدیث تزویـج رسول اللہ خدیـجۃ رضی اللہ عنھا والسیرۃ الـحلبیۃ باب ذکر وفاۃ عـمہٖ ابی طالب و زوجتِہِ خدیـجۃ رضی اللہ عنھا) حضرت عائشہؓ جوان بھی تھیں، خوبرو بھی
Page 140
تھیں، فرمانبردار اور وفا شعار بھی تھیں اور پھر وہ حضرت ابو بکر ؓ کی بیٹی تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ ؓ سے محبت تھی لیکن حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی ان باتوں سے عموماً چڑ جاتی تھی اور کہا کرتی تھی یا رسول اللہ آپ کو خدیجہؓ سے کئی اچھی بیویاں ملیں پھر آپ اس کو کیوں یاد کرتے ہیں مگر آپ ہمیشہ فرماتے عائشہ تمہیں معلوم نہیںخدیجہؓ نے کس وفاداری کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ کیا.تمہیں یہ باتیں بے شک بری لگتی ہیں لیکن میں مجبور ہوں کہ اس کا ذکر کروں یہ اس وقت کا حال ہے جب آپ نے نوجوان عورتوں سے شادیاں کی ہوئی تھیں.ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ ؓ آپ کے پاس تھیں جو حضرت ابو بکر ؓ کی بیٹی تھیں خوبصورت اور نو جوان تھیں اور آپ کی مخلص خادمہ تھیں کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی.کیا میں اندر آجاؤں یہ آنے والی حضرت خدیجہ ؓ کی چھوٹی بہن تھیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ یک دم متغیر ہو گیا.آپ بے قرار ہو کر اٹھے اور آپ نے فرمایا الٰہی میری خدیجہ! بہن کی آواز حضرت خدیجہؓ کی آواز سے ملتی تھی.آپ کو اس کی آواز سن کر حضرت خدیجہ یاد آگئیں اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا آئیں(بخاری کتاب مناقب الانصارباب تزویج النبی خدیجۃ و فضلھا).حالانکہ حضرت خدیجہؓ کی وفات پر اس وقت بارہ سال گذر چکے تھے یہ وہ وفاداری ہے جس کا نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا.اس وقت حسن کی یاد کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کیونکہ وہ ۶۵ سال کی عمر میں فوت ہوئی تھیں اگر کوئی نو جوان بیوی مر جائے تو خاوند اس کو یاد کرتا ہے لیکن یہاں تو صورت ہی اور تھی بیوی فوت ہوئی اور ایسی عمر میں فوت ہوئی کہ اس میں کوئی جسمانی دلکشی باقی نہیں رہی تھی.لیکن آپ کی محبت کا یہ حال ہے کہ بارہ سال بعد بھی آپ کے کان میں ایک آواز پڑتی ہے جو حضرت خدیجہ ؓ کی آواز سے ملتی جلتی ہے تو آپ کہہ اٹھتے ہیں.الٰہی میری خدیجہ!اور آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے.پھر یک دم کوئی خیال آیا اور فرمایا.تم فلاں تو نہیں ہو؟جواب ملا یا رسول اللہ میں ہوں خدیجہ کی بہن.یہ آپ کی وفادار ی کا ثبوت ہے جو آپ کو حضرت خدیجہ ؓ سے تھی اور یہ ایک ایسی بے نظیر چیزہے جس کی عوام میں تو کیا انبیاء میں بھی کوئی مثال نہیں مل سکتی.اس کی مثال عیسائی دنیا کیا پیش کر سکتی ہے.حضرت مسیح علیہ السلام نے تو۳۳ سال کی عمر تک جو انجیل سے ثابت ہے شادی ہی نہیں کی.ہاں آپ کے گرد جو ہر وقت عورتیں رہتی تھیں شبہ پڑتا ہے کہ وہ آپ کی بیویاں تھیں مگر یہ تو ایک مشتبہ بات ہے.پھر ان سے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی وفاداری کا کوئی سلوک ثابت نہیں وفادار ی کا شاندار مظاہرہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایسا کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے.
Page 141
(۴) پھر جب حضرت خدیجہؓ نے آپ سے شادی کی تو آپ سمجھ گئیں کہ میں مالدار ہوں اور یہ غریب ہیں.آپ کو جب ضرورت ہو گی مجھ سے مانگنا پڑے گا اور یہ بات شاید آپ برداشت نہ کر سکیں پھر زندگی کیسے گذرے گی.آپ بڑی ہو شیار اور سمجھ دار خاتون تھیںآپ نے خیال کیا کہ اگر ساری دولت آپ کی نذر کر دوں تو پھر آپ کو کوئی ایسا احساس نہیں ہو گا کہ یہ چیز بیوی نے مجھے دی ہے بلکہ آپ جس طرح چاہیں گے خرچ کر سکیں گے.چنانچہ شادی کو ابھی چند دن ہی گذرے تھے کہ حضرت خدیجہ ؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو پیش کروں.آپ نے فرمایا وہ کیا تجویز ہے.حضرت خدیجہ ؓ نے کہا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ساری دولت اور اپنے سارے غلام آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور یہ سب آپ کا مال ہوجائے.آپ قبول فرمالیں تو میری بڑی خوش قسمتی ہو گی.آپ نے جب یہ تجویز سنی تو آپ نے فرمایا خدیجہ ؓ کیا تم نے سوچ سمجھ لیا ہے؟اگر تم سارا مال مجھے دے دو گی تو مال میرا ہو جائے گا تمہارا نہیں رہے گا.حضرت خدیجہ ؓ نے عرض کیا میں نے سوچ کر ہی یہ بات کی ہے اور میں نے سمجھ لیا ہے کہ آرام سے زندگی گذارنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے.آپ نے فرمایا پھر سوچ لو حضرت خدیجہؓ نے عرض کیا ہاں ہاں میں نے خوب سوچ لیا ہے.آپ نے فرمایا اگر تم نے سوچ لیا ہے اور سارا مال اور سارے غلام مجھے دے دیئے ہیں تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے جیسا کوئی دوسرا انسان میرا غلام کہلائے.میں سب سے پہلے غلا موں کو آزاد کر دوں گا.حضرت خدیجہ ؓ نے عرض کیا اب یہ آپ کا مال ہے جس طرح آپ چاہیں کریں.آپ یہ سن کر بے انتہا خوش ہوئے.آپ باہر نکلے خانہ کعبہ میں آئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ خدیجہ ؓ نے اپنا سارا مال اور اپنے سارے غلام مجھے دے دیئے ہیں میں ان سب غلاموں کو آزاد کرتا ہوں.آج کل اگر کسی کو مال مل جائے تو وہ کہے گا چلو موٹر خرید لیں،کوٹھی بنا لیں،یوروپ کی سیر کریں.لیکن آپ کے اندر جو خواہش پید اہوئی وہ یہ تھی کہ جو میری طرح خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور عقل اور دماغ رکھتے ہیں وہ غلام ہو کر کیوں رہیں.عرب کے لحاظ سے ہی نہیں ساری دنیا کے لحاظ سے یہ ایک عجیب بات تھی مگر اس عجیب بات کا آپ نے اعلان فرمایا اور اس طرح آپ نے مال ملنے پر غیر معمولی سخاء کا ثبوت دیا.(۵) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میں تما م غلاموں کو آزا د کرتا ہوں تو اس پر اور تو سب غلام چلے گئے.صرف زید بن حارثہ ؓ جو بعد میں آپ کے بیٹے مشہور ہو گئے تھے وہ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا.آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا ہے مگر میں آزاد نہیں ہو نا چاہتا میں آپ کے پاس ہی رہوں گا.آپ نے اصرار کیا کہ وطن جاؤ اور اپنے رشتہ داروں سے ملو اب تم آزاد ہو.مگر حضرت زید ؓ نے عرض کیا جو محبت اور اخلاص میں
Page 142
نے آپ میں دیکھا ہے اس کی وجہ سے آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں.زید ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن چھوٹی عمر میں ان کو ڈاکو اٹھا لائے اور انہوں نے آپ کو آگے بیچ دیا.اس طرح پھرتے پھراتے وہ حضرت خدیجہؓ کے پاس آگئے.آپ کے باپ اور چچا کو بہت فکر ہوا اور وہ آپ کی تلاش میں نکلے.انہیں پتہ لگا کہ زید روما میں ہیں.وہاں گئے تو پتہ لگا کہ اب عرب میں ہیں، عرب آئے تو پتہ لگا کہ مکہ میں ہیں مکہ میں آئے تو پتہ لگا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں.وہ آپؐکے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کے پاس آپ کی شرافت اور سخاوت سن کر آئے ہیں.آپؐکے پاس ہمارا بیٹا غلام ہے اس کی قیمت جو کچھ آپ مانگیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں آپ اسے آزاد کر دیں اس کی ماں بڑھیاہے اور وہ جدائی کے صدمہ کی وجہ سے رو رو کر اندھی ہو گئی ہے.آپ کا بڑا احسان ہو گا اگر آپ منہ مانگی قیمت لے کر اسے آزاد کر دیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بیٹا میرا غلام نہیں میں اسے آزاد کر چکا ہوں پھر آپ نے زید کو بلایا اور فرمایا تمہارے ابا اور چچا تمہیں لینے کے لئے آئے ہیں تمہاری ماں بڑھیا ہے اور رو رو کر اندھی ہو گئی ہے.میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں تم میرے غلام نہیں ہو تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو.حضرت زید ؓ نے جواب دیا آپ نے تو مجھے آزاد کر دیاہے مگر میں تو آزاد ہو نا نہیں چاہتامیں تو اپنے آپ کو آپ کا غلام ہی سمجھتا ہوں.آپ نے پھر فرمایا تمہاری والدہ کو بہت تکلیف ہے اور دیکھو تمہارے ابا اور چچا کتنی دور سے اور کتنی تکلیف اٹھا کر تمہیں لینے آئیں ہیں تم ان کے ساتھ چلے جاؤ.زید ؓ کے والد اور چچا نے بھی بہت سمجھایا مگر حضرت زید نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور فرمایاآ پ بے شک میرے باپ اور چچا ہیں اور آپ کو مجھ سے محبت ہے مگر جو رشتہ میرا ان سے قائم ہو چکا ہے وہ اب ٹوٹ نہیں سکتا.مجھے یہ سن کر کہ میری والدہ سخت تکلیف میں ہیں بہت دکھ ہوا مگر ان سے جدا ہو کر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا.جب زید ؓ نے یہ باتیں کیں تو آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور اعلان کیا کہ زید نے جس محبت کا ثبوت دیا ہے اس کی وجہ سے آج سے وہ میرا بیٹا ہے.اس پر زید ؓکا باپ اور چچا دونوں خوش خوش واپس چلے گئے.کیونکہ انہوں نے دیکھ لیاکہ وہ نہایت آرام اور سکھ کی زندگی بسر کر رہا ہے.غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اخلاق کا یہ ثبوت ہے کہ جب زید ؓ نے وفاداری کا مظاہرہ کیا تو آپؐنے غیر معمولی احسان مندی کا ثبوت دیا.( الطبقات الکبرٰی لابن سعد طبقات البدریین من المھاجرین ذکر الطبقۃ الاولٰی ذکر زید الـحب) (۶) پھر جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے غیر معمولی انکسار کا ثبوت دیا.ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اگر کوئی الہام ہو تا ہے یا کوئی خواب آجاتی ہے تو وہ بے تحاشا دوسرے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور اسے
Page 143
بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ الہام ہو اہے یہ خواب آئی ہے مگر آپ کے پاس جبریل آتا ہے اور وہ کہتا ہے اِقْرَاْ پڑھ.تو آپ فرماتے ہیں مَا اَنَا بِقَارِئٍ میں تو پڑھنا نہیں جانتا.تین دفعہ آپ نے یہی کہا.مگر جب آپ نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر اصرار ہو رہا ہے تو پھر آپ نے حکم کی تعمیل کی اور ایسی جرأت سے کی کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ نہیں کہا کہ میرے رب مجھے کوئی اور ساتھی دے بلکہ آپؐنے اکیلے ہی اس بوجھ کو اٹھالیا اور مدد کے لئے کوئی ساتھی نہیں مانگا.(۷) پھر جب آپ نے اپنا دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آپ کی غیر معمولی مخالفت ہوئی اور اس کے مقابلہ میں آپ نے غیر معمولی صبر کا نمونہ دکھایا.آپ پر طرح طرح کے ظلم ہوئے.قسم قسم کی تکلیفیں آپ کو دی گئیں مگر آپ نے اس خاموشی کے ساتھ انہیں برداشت کیا کہ حیرت آتی ہے.ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کے باہر ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل آیا اور اس نے آپ کو بے تحاشا گالیاں دینی شروع کر دیں.آپ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا ہو اتھا.وہ گالیاں دیتا رہا اور آپ خاموشی سے سنتے رہے.جب اس کی گالیوں کا آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو ابو جہل کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا.اس کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی اس نے وہ سوٹی آپ کو ماری اور ساتھ ہی اور زیادہ گالیاں دینی شروع کر دیں.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا صرف اتنا کہا کہ میں نے آپ کا کیا قصور کیاہے صرف خدا تعالیٰ کا پیغام ہی آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں.لیکن اس کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا اور وہ آپ کو برابر گالیاں دیتا چلا گیا اور آخر تھک کر واپس چلا گیا.حضرت حمزہ ؓ کی ایک لونڈی تھی وہ یہ شور سن کر باہر نکل آئی اور اس نے گھر کے دروازہ سے یہ سارا نظارہ دیکھ لیا.اس کو یہ ظلم دیکھ کر سخت دکھ ہوا اور غصہ میں وہ ابلتی رہی.حضرت حمزہ ؓ شکار کرنے گئے ہوئے تھے.آپ کی زندگی سپاہیانہ تھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو انہوں نے سنی ہوئی تھیں مگر ان پر کبھی غور نہیں کیا تھا بس رات دن شکار میں لگے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ مزے کی زندگی ہے.شام کو اکڑتے ہوئے آپ شکا ر سے واپس آئے.کمان کندھے پر تھی ہاتھ میں شکار تھا اور آپ گھر میں اس طرح داخل ہورہے تھے جیسے کوئی جرنیل میدان مار کر گھر آتا ہے.وہ لونڈی اسی انتظار میں تھی کہ حمزہؓ شکار سے واپس آئیں تو میں ان سے بات کروں.پرانی لونڈیاں گھروں میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے رشتہ داروں کی طرح ہو جاتی تھیں اور بے تکلفی سے بات کر لیتی تھیں.اس لونڈی نے آپ کو دیکھ کر کہا.بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں جانور مارنا بھی کوئی کا م ہے ایسا تو ہر کوئی کر سکتا ہے.آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے گالیاں دیں اور مارا اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا.اس نے اُف تک نہیں کی.مگر تم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور ہر وقت شکار کے خیال میں لگے رہتے ہو.
Page 144
حضرت حمزہ ؓ نے پو چھا کیا ہوا.لونڈی نے سارا واقعہ سنا دیا.آخر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشہ دار تھے اور آپ کی باتیں انہوں نے سنی ہوئی تھیں مگر کبھی غور نہیں کیا تھا.اب جو یہ واقعہ ہوا تو غیرت جوش میں آگئی اور وہ اسی وقت واپس گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچے جہاں ابو جہل اور مکہ کے دوسرے رؤوسا بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہے تھے.انہوں نے جب حضرت حمزہ ؓ کو دیکھا تو آپ کے بیٹھنے کے لئے جگہ بنادی کیونکہ وہ بھی ایک رئیس تھے.مگر حضرت حمزہ ؓ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی.اور آگے بڑھ کر ابو جہل کے منہ پر کمان مار کر کہا تو نے آج میرے بھتیجے کو مارا ہے.اس نے تجھے کچھ نہیں کہا.لیکن اب میں نے ساری قوم کے سامنے تیرے منہ پر کمان ماری ہے اگر ہمت ہے تو مجھے مار.مذہبی تعصب کی وجہ سے دوسرے رؤوسا کو غصہ آگیا اور انہوں نے حضرت حمزہ ؓ کو مارنا چاہا مگر ابو جہل نے رو ک دیا اور کہا واقعہ میں آج مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی تھی اور میں اسے محسوس کرتا ہوں.اس کے بعد اسی جوش کی حالت میں حضرت حمزہ ؓ خانہ کعبہ سے لوٹے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں.یہ ایمان جو حضرت حمزہ ؓ کو نصیب ہوا کس بات کا نتیجہ تھا.اسی غیر معمولی صبر کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا.( السیرۃ الحلبیۃ باب استخفائہ واصحابہ فی دار الارقم) (۸) جب لوگوں نے آپ کی باتیں سننے سے انکار کر دیا تو آپ مایوس نہیں ہوئے.ایسی حالت میں عام طور پر کمزور لوگ گھبرا کر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ لوگ تو ہماری باتیں سنتے ہی نہیں ہم تبلیغ کسے کریں.مگر آپ گھبرائے نہیں بلکہ استقلال کے ساتھ آپ نے اپنے کام کو جاری رکھا.آپ اپنی زندگی اس غرض کے لئے وقف سمجھتے تھے اور دن رات اسی کام میں لگے رہتے تھے.عکاظ کے میلہ پر آپ جاتے اور خدائے واحد کی تبلیغ کرتے.اسی طرح جہاں کہیں آپ کو کچھ آدمی اکٹھے نظر آتے آپ ان کے پاس پہنچ جاتے اور فرماتے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خدا تعالیٰ کی باتیں سناؤں مکہ والوں نے لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ آپ پاگل ہیں.جب آپ کہتے کہ اگر آپ چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کی باتیں آپ کو سناؤں تو وہ ایک دوسرے کو آنکھ مار کر کہتے کہ یہ وہی مکہ والا پاگل ہے اور کھسک جاتے.پھر آپ دوسرے گروہ کے پاس جاتے اور فرماتے اگر آپ چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کی باتیں آپ کو سناؤں.وہ بھی یہ بات سنتے اور آنکھ مار کر ایک دوسرے سے کہتے یہ وہی مکہ کا پاگل ہے اور کھسک جاتے.اس طرح آپ سارا دن وہاں چکر لگاتے رہتے.کبھی ایک گروہ کے پا س جاتے اور کبھی دوسرے کے پاس.مگر لوگ آپ کی باتیں سننے سے انکار کر دیتے.لیکن پھر انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو آپ پر ایمان لائے اور جنہوں نے
Page 145
اسلام کی نہایت شاندار خدمات سر انجام دیں.یہ وہ غیر معمولی استقلا ل تھا جس نے آپ کو کامیاب کیا اور یہی وہ استقلال ہے جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے.حقیقت یہ ہے کہ جب تک دیوانگی اور جنون پیدا نہ ہو اس وقت تک تبلیغ کامیاب نہیں ہو اکرتی.(البدایۃ والنـھایۃ فَصْلٌ فِي عَرْضِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ عَلَى أحياء العرب) (۹) جب لوگوں نے آپ کو ایذائیں دیں اور آ پ پر مظالم توڑے تو آپ نے غیر معمولی ضبط نفس اور خیرخواہی کا ثبوت دیا.آپ جب طائف تشریف لے گئے اور لوگوں کو تبلیغ کی تو انہوں نے آپ کے پیچھے کتے لگا دیئے اور آپ پر پتھراؤ کیا.آپ واپس تشریف لے آئے.مگر ایسی حالت میں کہ لوگ آپ کو پتھر مارتے جاتے تھے اور آپ کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے.یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے فرشتوں کو حکم دیاکہ جاؤ اور میرے رسول کی مدد کرو.چنانچہ آپ کو ایک فرشتہ دکھائی دیا اور اس نے کہا میں اس پہاڑی پر مقرر ہوں جو آپ کے سامنے ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لئے بھیجا ہے.اگر حکم ہو تو اس پہاڑی کو اٹھا کر طائف والوں پر پھینک دوں اور انہیں تباہ کر دوں.آپ نے فرمایا.نہیں نہیں.اگر یہ لوگ تباہ ہو گئے تو پھر ایمان کون لائے گا.سر سے پاؤں تک آپ زخمی ہیں،ٹخنوں سے خون بہہ رہاہے.مگر ہمدردی کا یہ عالم ہے کہ اس حالت میں بھی طائف والوں کی خیر خواہی مدّ ِنظر ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہوں.مکہ والوں نے کچھ جائیداد طائف کے پاس بھی خریدی ہوئی تھی.چونکہ طائف کی زمین میں زراعت ہوسکتی تھی اس لئے مکہ کے رؤوسا نے وہاں زمینیں خریدی ہوئی تھیں اور باغ وغیرہ لگائے ہوئے تھے طائف سے سات آٹھ میل باہر مکہ کے ایک رئیس کا باغ تھا جو آپ کا شدید ترین دشمن تھا وہاں آکر آپ بیٹھ گئے.زید ؓ بھی آپ کے ساتھ تھے.وہ رئیس اس نظارہ کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا.اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور کہا وہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں باغ سے اچھے اچھے انگور توڑ کر انہیں کھلاؤ.وہ غلام نینوا کا باشندہ تھا.جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟اس غلام نے جواب دیا میں نینوا کا باشندہ ہوں.آپ نے فرمایااچھا تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے ملک کے ہو آؤ میں تمہیں خدا تعالیٰ کی باتیں سناؤں.آپ کو اپنے زخم بھول گئے،بھاگنا بھول گیا،تھکاوٹ بھول گئی اور تبلیغ شروع کر دی.وہ غلام عیسائی تھا اور اس نے آنے والے موعود کے متعلق باتیں سنی ہوئی تھیں.اس پر آپ کی تبلیغ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ آپ کے قدموںمیں جا پڑا اور اپنے بالوں سے آپ کے پاؤں کا خون پونچنے لگا اور انہیں چومنے لگ گیا.آپ کا دشمن رئیس بھی اس کے پیچھے آیا.اس سے ہمدردی کا
Page 146
اثر زائل ہو چکا تھا.اس نے غلام سے کہا یہ تو مکہ کا پاگل ہے اور میرا رشتہ دار ہے اس کی باتوں میں نہ آجانا.اس غلام نے کہا نہیں یہ پاگل نہیں.اس کی باتیں تو نبیوں والی باتیں ہیں( السیرۃ الحلبیۃ ذکر خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الطائف ) دیکھو آپ میں کتنی خیر خواہی کا جذبہ تھا اور پھر کتنا غیر معمولی ضبط آپ میں پایا جاتا تھا.ایک طرف آپ پر طائف والے ظلم کر رہے تھے،انہوں نے کتے چھوڑے ہوئے تھے،پتھراؤ کر رہے تھے اور دوسری طرف آپ ان کے لئے دعائیں کر رہے تھے کہ اے میرے رب تو ان پر رحم کر یہ جانتے نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں اگر جانتے تو یہ کام نہ کرتے.(۱۰) پھرجب صحابہؓ پر ظلم ہوئے تو آپ نے کتنی خیر خواہی کا ثبوت دیا.دوسرے لوگوں پر ظلم ہوتے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو پاس بلا لیتے ہیں تا کہ جتھہ بن جائے اور لوگ زیادہ تکلیف نہ دے سکیں.مگر آپ نے صحابہ ؓ کو بلا کر کہا تم ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جاؤ مجھ پر جو گذرے گی گذر جائے گی.چنانچہ اکثر صحابہ ؓ ہجرت کر گئے اور آپ صرف چند صحابہ ؓ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے.( السیرۃ النبویۃ لابن ھشام ذکر الھجرۃ الاولٰی الی ارض الحبشۃ) (۱۱) پھر جب ہجرت کا وقت آیا تو مکہ جیسا عزیز وطن جس کی وجہ سے آپ کے آباء و اجداد کی عزت چلی آئی تھی جس میں خانہ کعبہ تھا جس میں آپ کبھی کبھار عبادت کر لیا کرتے تھے اس کی آپ نے قربانی کی اور ایسی دلیری سے کی کہ اس حب الوطنی کی قربانی کی مثال بھی کسی اور جگہ نہیں مل سکتی.آپ کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی یہ اس بات سے ظاہر ہے کہ جب آپ غار ثور سے نکلے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا.خدا لعنت کرے اس شہر والوں پر جنہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی اور اس کو شہر سے نکال دیا.آپ ؐ نے فرمایا.ابو بکرؓ ایسا مت کہو.پھر آپ نے مکہ کی طرف دیکھا اور فرمایا اے مکہ! تو مجھے بہت ہی پیارا ہے.مگر تیرے بسنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا.کیسی اعلیٰ درجہ کی حب الوطنی کی مثال ہے جو آپ ؐ نے پیش کی ہے.مگر پھر اس محبت کو خدا تعالیٰ کے لئے کس دلیری اور جرأت کے ساتھ قربان کر دیا.(۱۲) پھر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کی عقل کا کمال ظاہر ہوا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جاتے ہی مدینہ والوں کی تنظیم کی.انہیں اکٹھا کیا اور یہودیوں سے معاہدات کئے.تا کہ ان کی شرارتوں کا سدِّ باب ہو.اس طرح آپ کی غیر معمولی ذہانت اور دانشمندی کا ثبوت ملا.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ موقع کہاں ملا.آپ کی زندگی تو غلامی میں ہی گذر گئی.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جاتے ہی مدینہ والوں کی تنظیم کی.یہودیوں سے معاہدات کئے.مہاجرین کے حقوق قائم کئے اور ایسا عقل کا ثبوت دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں مل
Page 147
سکتی.مکہ میں آپ کو ایک محلہ کی بھی تنظیم کا موقعہ نہیں ملا تھا مگر یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ پہلے ہی بادشاہ تھے اور تنظیم کا دیرینہ ملکہ رکھتے تھے.چنانچہ وہ مدینہ والے جو ہر وقت دوسرے قبائل سے پٹتے رہتے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے اس تنظیم کی بدولت عرب کی ایک بڑی طاقت بن گئے.( السیرۃ النبویۃ لابن ھشام باب ھجرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم) (۱۳) پھر لڑائیاں شروع ہوئیں تو ان میں آپؐنے غیر معمولی بہادری کا ثبوت دیا.اگر آپ حکومت ملنے سے پہلے فوت ہو جاتے تو لوگ سمجھتے کہ آپ کمزور تھے.اس لئے آپ نے دکھوں کو بر داشت کر لیا مگر حکومت ملنے کے بعد آپ نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ میرا معاف کرنا کمزوری کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ وسعت حوصلہ کی وجہ سے تھا.آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے اپنی ذلت محسوس کر کے آپ کے چاروں طرف لشکر پھیلانے شروع کر دیئے جس کی وجہ سے آپ کو بھی ان کے مقابلہ کے لئے نکلنا پڑا لیکن ان لڑائیوں میں بھی آپ نے بےمثال نمونہ قائم فرمایا.بڑے بڑے بادشاہ بھی شب خون مار لیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی شب خون نہیں مارا.آپ کی غیر معمولی ذہانت کا ایک بڑا نمونہ اس میں ملتا ہے کہ آپ نے آٹھ سال تک لڑائیاں کیں اور درجنوں کیں مگر ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا ہو اور کفار کو پتہ لگ گیاہو اور ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا جب کفار نے حملہ کیا ہو اور آپ کو پہلے پتہ نہ لگ گیا ہو.کتنی بڑی ذہانت ہے کتنی بڑی ہو شیاری ہے.عجیب بات یہ ہے کہ کفار نے خود حملہ کی تیاریاں کیں اور آپ کو پتہ لگ گیا.بنی مصطلق نے ایک لشکر تیار کیا اور جنگی تیاریاں مکمل کر لیں تا کہ آپ پر اچانک حملہ کر دیا جائے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دس بارہ منزل پر تھے مگر وہ تو ابھی تیاریوں میں مشغول تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی مصطلق پر اس حالت میں حملہ آور ہو گئے کہ ان کی عورتیں ابھی آٹا گوندھ رہی تھیں اور ان کو اس حملے کا خیال تک نہ تھا(البدایۃ والنـھایۃ غزوۃ بنی المصطلق ) پھر آپ جب فتح مکہ کے لئے گئے تو آپ کا یہ جانا ایسا اچانک تھا کہ کفار نے دور سے لشکر دیکھ کر ابو سفیان سے پو چھا کہ یہ کہیں اسلامی لشکر تو نہیں؟ابو سفیان نے کہا میں تو ابھی مدینہ سے آرہا ہوں ان کی تو حملہ کی کوئی تیاری ہی نہیں تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اسلامی لشکر ہو لیکن ابو سفیان ابھی باتیں ہی کر رہا تھا کہ اسلامی سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا.مکہ والے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ابو سفیان مدینہ گیا ہو اہے ابھی لڑائی کہاں ہو سکتی ہے.مگر دوسرے ہی دن ایک لشکر جرار کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے.غرض آٹھ سال کی درجنوں لڑائیوں میں کوئی بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے حملہ کیا ہو اور دشمن کو پہلے پتہ لگ گیا ہو یا دشمن نے حملہ کیا ہو اور آپ کو
Page 148
پہلے پتہ نہ لگ گیا ہو.اس کی مثال نہ دنیاوی تاریخوں میں ملتی ہے اور نہ مذہبی تاریخوں میں ملتی ہے.(۱۴) پھر آپ جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے غیر معمولی استغناء اور تقویٰ کا بھی ثبوت ملا.آپ نے ایک ٹکڑہ زمین پسند کیا جو یتیموں کا تھا.آپ نے اس کے مالک کو بلایا.وہ آیا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ زمین میرے یتیم بھتیجوں کی ہے اور میں اس کا نگران ہوں.میرے یتیم بھتیجے خوشی سے یہ زمین آپ کو دیتے ہیں.آپ نے فرمایا ہم یتیموں کا مال نہیں لے سکتے.ہاں قیمت مقرر کرو تب لیں گے.(۱۵) دوسروں کے جذبات کا آپؐاس طرح خیال رکھتے تھے کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہرے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر کی منزل میں رہیں ہم نیچے کی منزل میں رہتے ہیں.آپ نے فرمایا نہیں میں نیچے کی منزل میں ہی رہوں گا.مجھے آدمی ملنے کے لئے آئیں گے تو آپ کو تکلیف ہو گی.حضرت ابو ایوب انصاریؓ نے عرض کیا.یا رسول اللہ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ نیچے رہیں اور میں اوپر رہوں.آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں نچلی منزل میں ہی رہوں گا.ایک رات چھت پر غلطی سے کچھ پانی گر گیا اور یہ خطرہ محسوس ہو اکہ کہیں پانی ٹپک کر نیچے نہ چلا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو.حضرت ابو ایوب انصاریؓ اور ان کی بیوی نے فوراً اپنے لحاف اتار کر پانی میںڈال دیئے اور اس کو خشک کیا اور خود ساری رات ننگے بیٹھے رہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ نے فرمایا اچھا میں اوپر چلا جاتا ہوں تم نیچے آجاؤ.گویا دونوں حالتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق کا مظاہرہ کیا.پہلے آپ نے اس لئے اوپر کی منزل میں رہائش اختیار نہ کی کہ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاریؓ کو تکلیف ہو گی اور جب آپ کو ان کی ایک دوسری تکلیف کا علم ہوا تو پھر آپ نے اوپر کی منزل میں رہنا منظور کر لیا تا کہ ان کو تکلیف نہ ہو.( البدایۃ والنـھایۃ فصل فی دخولہ المدینۃ و این استقر منزلہ) (۱۶) اس کے بعد ہم آپ کے جذبہ توحید کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں آپ کا بے مثال نمونہ نظر آتا ہے.یوں تو ہر نبی دنیا میں اسی غرض کے لئے آتا ہے کہ خدائے واحد پر ایمان قائم ہو اور دنیا کے تما م مذاہب اس کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں.صرف عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس کے پیرو آج کل یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تثلیث کا عقیدہ قائم کر نے کے لئے آئے تھے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی باتوں سے جو اناجیل میں درج ہیں تثلیث کا پتہ نہیں لگتا.بلکہ ان کا مطالعہ انسان پر اسی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ وہ توحید کے قیام کے لئے مبعوث
Page 149
ہوئے تھے.آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ میں تورات یا دوسرے نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں.منسوخ کرنے نہیں بلکہ پور اکرنے آیا ہوں(متی باب ۵ آیت ۱۷) اور جب وہ تورات کی تعلیم کے تابع تھے اور تورات کا ایک شوشہ بھی بدل نہیں سکتے تھے تو تورات میںتوحید کا ہی ذکر ہے تثلیث کا ذکر نہیں.بہر حال ہر نبی دنیامیں توحید کے قیام کے لئے مبعوث ہو تا ہے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ میں توحید کو قائم کیا ہے اور جو جذبہ غیرت اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق آپ کے اندر پایا جاتا تھا اس کی مثال کسی اور نبی میںہمیں نظر نہیں آتی.حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کو اس رنگ میں پیش کیا کہ اس سے شرک کا شبہ پیدا ہو گیا.یہی وجہ ہے کہ عیسائی رفتہ رفتہ مشرک ہو گئے اور وہ توحید کو کلی طور پر چھوڑ بیٹھے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں میں بھی کچھ شرک پیدا ہو گیا ہے.لیکن مسلمانوں میں جو شرک پایا جاتاہے وہ جُہّال کا شر ک ہے.خواہ یہ جاہل طبقہ عوام الناس میں سے ہو یا علماء کہلانے والوں میں سے ہومگر عیسائیت میں جو شرک پایا جاتا ہے وہ ان کے چوٹی کے علماء میں بھی پایا جاتا ہے.پھر مسلمانوں کے شرک اور اس شرک میں ایک اور فرق یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرک پیدا ہو جانے کے باوجود اس کے مخالف علماء پائے جاتے رہے ہیں.مثلاً سید عبدالقادر صاحب جیلانیؒ ہیں.ان کی کتابوں میں تو حید ہی توحید بھری ہو ئی ہے.اب اگر ان کے معتقد شرک کرنے لگ جائیں تو کوئی دھوکا نہیں لگ سکتا.اگر کوئی کہے گا کہ میں جیلانی صاحبؒکا معتقد ہوں تو ہم آپ کی کتابیں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ دیکھو آپ تو بڑے مؤحد تھے تمہیں بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے گویا مسلمانوں کی غلطیوں کو ظاہرکرنے کے مواقع موجود ہیں مگر عیسائیت کو لو تو ان کے بڑے سے بڑے عالم حتی کہ پوپ میں بھی شرک موجود ہے اور اس پوپ سے دس درجے پہلے جو پوپ تھا اس میں بھی شرک پا یا جا تا تھا.یہ جُہّال کا شرک نہیں بلکہ چوٹی کے علماء میں بھی یہ شرک پایا جاتا ہے.اس وجہ سے مسلمانوں پر ان کی غلطی کو واضح کرنا آسان بات ہے مگر عیسائیوں پر ان کی غلطی کو ظاہر کرنا آسان بات نہیں.بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیرت کا جو آپ کو توحید کے متعلق تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نازک سے نازک مواقع پر بھی توحید کا سبق دیا.جنگ احد کے مو قعہ پر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے فتح دی اور کفار بھاگ گئے.خالدؓ بن ولید اور عمروؓ بن عاص جو اسلام کے عظیم الشان جرنیل گذرے ہیں ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور اس جنگ میں کفار کی طرف سے شامل تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کے ایک گروہ کو ایک درہ میں کھڑا کیا اور انہیں تاکیدی حکم دیا کہ تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا خواہ ہمیںفتح ہو یا شکست.ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنامسلمانوں میں جہاد کا جوش تھا اور اب بھی ہے.جب اسلام کو فتح حاصل ہوئی تو جو
Page 150
لوگ اس درے پر کھڑے تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ ہمیں بھی تھوڑا بہت جہاد میں حصہ لینے کی اجازت دیں.اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا.اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ خواہ فتح ہو یا شکست.ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں.اس جگہ سے نہ ہلیں.اس لئے ہمیں یہیں رہنا چاہیے.انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ خواہ فتح ہو جائے تب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا.آپ نے تو ہمیں احتیاطاً یہاں کھڑا کر دیا تھا.دشمن اب بھاگ گیا ہے اور اسلام کو فتح حاصل ہو گئی ہے.اب اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور جہاد میں تھوڑا بہت حصہ لے لیں.افسر نے کہا جب حاکم حکم دے دیتا ہے تو ماتحت کا یہ حق نہیں ہو تا کہ وہ اپنی عقل کو دوڑائے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہاں سے نہیں ہلنا.خواہ فتح ہو یا شکست.ہم مارے جائیں یا زندہ رہیں اور تاکید فرمائی تھی کہ اس جگہ کو نہ چھوڑا جائے اس لئے آپ کی ہدایت کے مطابق ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے.مگر انہوں نے یہ بات نہ مانی اور اپنی غلطی پر انہوں نے اس قدر اصرا ر کیا کہ اپنے افسر سے کہا.آپ ٹھہرے رہیں ہم تو جاتے ہیں.چنانچہ اکثر ان میں سے چلے گئے.صرف افسر اور اس کے چند ساتھی باقی رہ گئے.جب کفار کا لشکر بھاگا.خالدؓ بن ولید بڑے ذہین اور ہو شیار تھے.اسلام میں بھی آپ نے شاندار کام کئے ہیں اور کفار میں بھی آپ بڑے پایہ کے جر نیل تھے.آپ جب اپنے لشکر کے ساتھ بھاگے جارہے تھے تو اچانک ان کی نگاہ اس درہ پر پڑی اور وہ خالی نظر آیا.آپ کے ساتھ عمروؓ بن العاص بھی تھے.آپ نے عمروؓ سے کہا ہمیں اعلیٰ درجہ کا موقعہ مل گیا ہے.عمرو ؓ نے بھی اس طرف دیکھا اور دونوں اپنا دستہ لے کر واپس لوٹے.خالدؓ بن ولید نے ایک طرف سے چکر لگاکر درہ پر حملہ کیا اور عمر وؓ بن عاص نے دوسری طرف سے.اور درہ پر جو چند آدمی موجود تھے ان کو مار کر انہوں نے مسلمانوں پر پشت کی طرف سے حملہ کر دیا.مسلمان اس درہ کی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اورتتر بتر ہو چکے تھے صفیں ٹوٹ چکیں تھیں اور بچے کھچے دشمن کا پیچھا کر رہے تھے جب خالدؓ بن ولید اور عمروؓبن عاص نے ان کی پیٹھ پر حملہ کیا تو اکیلا اکیلا مسلمان پورے دستہ کے سامنے آگیا.کچھ مسلمان مارے گئے اور کچھ زخمی ہوگئے اور باقیوں کے پاؤں اکھڑ گئے خصوصاً جب حملہ کرتے کرتے دشمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ کے پاس اس وقت صرف بارہ آدمی تھے.ان دونوں جرنیلوں یعنی خالدؓ بن ولید اور عمروؓ بن عاص نے اپنے دوسرے افسروں کو بھی اطلاع کر دی تھی کہ تم بھی حملہ کر دو چنانچہ تین ہزار کا لشکر ریلا کرتے ہوئے آگیا اس وقت دشمن کی طرف سے پتھراؤ ہورہا تھا تیر برس رہے تھے تلواریں چل رہیں تھیں اور تمام اسلامی لشکر میں ایک بھاگڑ اور کھلبلی مچی ہوئی تھی ایسی حالت میں صحابہ ؓ نے بے نظیر قربانیاں
Page 151
کیں مگر تین ہزار کے تازہ دم لشکر کے سامنے وہ تاب نہ لا سکے اس حملہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت بھی ٹوٹے اور آپ کی خود میں بھی ایک پتھر لگا جس کی وجہ سے خود کا ایک کیل آپ کے سر میں دھنس گیا جس سے آپ بے ہوش کر ایک گڑھے میں گر گئے آپ کے پاس جو صحابہؓ کھڑے تھے ان کی لاشیں آپ کے اوپر آپڑیں اور آپ کا جسم اطہر نیچے چھپ گیا.اور مسلمانوں میں شور مچ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں مسلمانوں کے قدم پہلے ہی اکھڑے ہوئے تھے اس خبر نے ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا کردیئے.مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب کفار میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے مزید حملہ نہ کیا.بلکہ یہی مناسب سمجھا کہ اب جلدی مکہ کو لوٹ چلیں اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں کہ نعوذ با للہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں.جب مسلمانوں کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو وہ جلدی جلدی واپس لوٹے اور انہوں نے آپ کے اوپر سے لاشوں کو ہٹایا.معلوم ہو اکہ آپ ابھی زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں.اس وقت سب سے پہلے آپ کے خود کاکیل نکالا گیا یہ کیل نکلتا نہیں تھا آخر ایک صحابی ؓ نے اپنے دانتوں سے نکالا جس کی وجہ سے ان کے دو دانت ٹوٹ گئے پھر آپ کے منہ پر پانی چھڑ کا گیا تو آپؐہو ش میں آگئے اکثر صحابہ ؓ تو تتر بتر ہو چکے تھے صرف چند صحابہ کا گروہ آپ کے پاس تھا.آپ نے ان سے فرمایا ہمیں اب پہاڑ کے دامن میں چلے جانا چاہیے چنانچہ آپ ان کو لےکر ایک پہاڑی کے دامن میں چلے گئے اور پھر باقی لشکر بھی آہستہ آہستہ اکٹھا ہو نا شروع ہوا کفار کا لشکر جب واپس جا رہا تھا تو ابو سفیان نے بلند آواز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور کہا ہم نے اسے مار دیا ہے صحابہؓ نے جواب دینا چاہا مگر آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا یہ موقعہ نہیں ہمارے آدمی تتر بتر ہوچکے ہیں کچھ مارے گئے ہیں اور کچھ زخمی ہیں ہم تھوڑے سے آدمی یہاں ہیں اور پھر تھکے ماندے ہیں.کفار کا لشکر تین ہزار کا ہے اور وہ بالکل سلامت ہے ایسی حالت میں جواب دینا مناسب نہیںوہ اگر کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مار دیا ہے تو کہنے دو.چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق صحابہؓ خاموش رہے.جب ابو سفیان کو کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا ہم نے ابوبکرؓ کو بھی مار دیا ہے.آپ نے صحابہ ؓ کو پھر جواب دینے سے روک دیا اور فرمایا خاموش رہو.وہ کہتا ہے تو کہنے دو چنانچہ صحابہؓ اس پر بھی خاموش رہے.ابو سفیان کو جب پھر کوئی جواب نہ ملا توا س نے کہا ہم نے عمرؓ کو بھی مار دیا ہے حضرت عمرؓ بڑے تیز طبیعت کے تھے.آپ بولنے لگے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کر دیا.بعد میں آپ نے بتایا کہ میں کہنے لگا تھا کہ تم کہتے ہو ہم نے عمرؓ کو مار دیا ہے حالانکہ عمرؓاب بھی تمہارا سر
Page 152
توڑنے کے لئے موجود ہے.بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جواب دینے سے منع کر دیاجب ابوسفیان نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے نعرہ مارا اُعْلُ ھُبُلْ.اُعْلُ ھُبُلْ یعنی ہبل دیوتا جسے ابو سفیان بڑا سمجھتا تھا اس کی شان بلند ہو.ہبل کی شان بلندہو(یعنی آخر ہمارے ہبل نے محمد(صلی اللہ علیہ وسلم )اور اس کے ساتھیوں کو مار ہی دیا) صحابہؓ کو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے اور جواب دینے سے منع فرمایا تھا اس لئے وہ اب بھی خاموش رہے مگر خدا کا وہ رسول جس نے اپنی موت کی خبر سن کر کہا تھا کہ خاموش رہوجواب مت دو، حضرت ابوبکرؓ کی موت کی خبر سن کر کہا تھا خاموش رہو جواب مت دو، حضرت عمرؓ کی موت کی خبر سن کر کہا تھا خاموش رہو جواب مت دو اور جوباربار کہتا تھا کہ اس وقت ہمارا لشکر پراگندہ ہے اور خطرہ ہے کہ دشمن پھر حملہ نہ کردے اس لئے خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے چلے جاؤ.اس مقدس انسان کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی اُعْلُ ھُبُلْ.اُعْلُ ھُبُلْ.ہبل کی شان بلند ہو.ہبل کی شان بلند ہو.توا س کے جذبہ توحید نے جوش مارا کیونکہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال نہیں تھا.اب ابوبکرؓ اور عمرؓ کا سوال نہیں تھا.اب اللہ تعالیٰ کی عزت کا سوال تھا.آپ نے بڑے جوش سے فرمایاتم کیوں جواب نہیں دیتے.صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟آ پ نے فرمایا کہو اَللہُ عَزَّوَجَلَّ.اَللہُ عَزَّوَجَلَّ ہبل کیا چیز ہے.خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے خدا تعالیٰ کی شان بلند ہے.یہ کتنا شاندار مظاہرہ آپ کے جذبہ توحید کا ہے.آپ نے تین دفعہ صحابہؓ کو جواب دینے سے روکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو خطرہ کی اہمیت کا پورا احساس تھا.آپ جانتے تھے کہ اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا ہے اور بہت کم لوگ آپ کے ساتھ ہیں.اکثر صحابہ زخمی ہوگئے ہیں اور باقی تھکے ہوئے ہیں.اگر دشمن کو یہ معلوم ہوگیا کہ اسلامی لشکر کا ایک حصہ جمع ہے تو وہ کہیں پھر حملہ کرنے کی جرأت نہ کرے.مگر ان حالات کے باوجود جب خدتعالیٰ کی عزت کا سوال آیا تو آپ نے خاموش رہنا برداشت نہ کیا اور سمجھا کہ دشمن کوخواہ پتہ لگے یا نہ لگے.خواہ وہ حملہ کرے اور ہمیں ہلاک کردے.اب ہم خاموش نہیں رہیں گے.چنانچہ آپ نے صحابہؓ سے فرمایا تم خاموش کیوں ہو جواب کیوں نہیں دیتے کہ اَللہُ عَزَّوَجَلَّ.اَللہُ عَزَّوَجَلَّ.( السیرۃ الـحلبیۃ غزوۃ احد و السیرۃ النبویۃ لابن ھشام و خبر عاصم بن ثابت وبـخاری کتاب الـجھاد و السیر باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الـحرب.....) (۱۷) کمزوروں کی حفاظت کا جذبہ بھی آپ کے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا تھا.جنگ احزاب میں کفار کی تعداد پندرہ ہزار کی تھی.اور مسلمان لشکر کی تعداد صرف بارہ سو.بعض نے دشمن کا اندازہ اس سے زیادہ بتایا ہے اور بعض نے کم.یوروپ والے صرف دس ہزار بتاتے ہیں تاکہ بڑے لشکر کی شکست سے وہ شرمندہ نہ ہوں.اس کے مقابلہ
Page 153
میں بعض مسلمانوں نے ۲۴ ہزار تک بھی تعداد لکھی ہے لیکن میرا اندازہ پندرہ ہزار کے قریب قریب ہے.اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی بھی مختلف تعدادیں بتائی گئی ہیں.بعض نے مسلمانوں کی تعداد زیادہ بتائی ہے اور بعض نے کم بتائی ہے لیکن مجھے جہاں تک تاریخوں کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے اسلامی لشکر کی بارہ سو کی تعداد زیادہ درست معلوم ہوتی ہے.اس جنگ میں کفار نے مدینہ کے ایک یہودی قبیلہ سے جو باقی رہ گیا تھا خفیہ معاہدہ کر لیا کہ جب حملہ بڑھ جائے تو وہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں.مدینہ کے ایک طرف میدان تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی ہوئی تھی.ایک طرف یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا.آپ نے خیال کیا کہ یہ قبیلہ بھی ہمارے ساتھ ہے اس لئے یہ طرف بھی محفوظ ہے.تیسری طرف ایک پہاڑ تھا جس کے متعلق خیال تھا کہ دشمن اس طرف سے نہیں آئے گا اور اگر آیا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا اور ہم ان کے حملہ کو روک سکیں گے چوتھی طرف متواتر مکان واقع تھے اور ایک دیوار سی بنی ہوئی تھی.گویا ایک طرف پہاڑ کی حفاظت تھی.دوسری طرف معاہد یہودی قبیلہ تھا.ایک طرف مکانوں کی دیوار بنی ہوئی تھی اور ایک طرف میدان تھا جس میں آپ نے خندق کھدوائی تھی.جب کفار کے لشکر نے دیکھا کہ سامنے سے مقابلہ کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوسکتے تو انہوں نے یہودیوں سے سازباز کی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی طرف سے مطمئن تھے.انصارؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ یہودیوں کا اعتبار نہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.ہمارا ان سے معاہدہ ہے تم کیوں ان پر بد ظنی کرتے ہو.مگر جب زیادہ خبریں آنی شروع ہوگئیں تو دو انصاری صحابی جو ان سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے پتہ لینے کے لئے بھجوائے گئے.ان سے جو یہودیوں نے باتیں کیں ان سے معلوم ہوتاتھا کہ وہ ضرور غداری کر جائیں گے.ان دو صحابیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رپورٹ کی کہ حالات اچھے نظر نہیں آتے لیکن آپ نے پھر بھی معاہدہ کا احترام کیا اور فرمایا ہمارا حق نہیں کہ ہم معاہدہ توڑیں( السیرۃ النبویۃ لابن ھشام غزوۃ خندق والبدایۃ والنـھایۃ غزوۃ خندق) ان ایام میں آپ نے عورتوں کو حفاظت کے لئے دو جگہ پر اکٹھا کر دیا تھا کچھ عورتوں کو تو دو منزلہ مکانات پر جمع کر دیا گیا تھا اور اپنے خاندان کی عورتوں یا ان صحابہ کی عورتوں کو جن کے متعلق خیال تھا کہ دشمن زیادہ زور کے ساتھ ان پر حملہ کرے گا اور جن کی بے حر متی سے قوم کی بے حر متی ہو سکتی تھی ان کو آ پ نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا تھا.وہ جگہ جہاں یہ عورتیں جمع تھیں یہودیوں کی طرف تھی.حضرت صفیہ ؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں ایک دفعہ پھر رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی دیوار پر سے جھانک رہا ہے.حضرت صفیہ ؓ نے حسان بن ثابتؓ
Page 154
کو جو پہرہ پر مقرر تھے کہا کہ ایک یہودی دیوار سے جھانک رہاہے اٹھو اور اس کو مارو حضرت حسان ؓ کمزور دل آدمی تھے انہوں نے کہا کہ کوئی راہ گیر ہو گا آپ کو یوں ہی وہم ہو گیا ہے.حضرت صفیہ ؓ نے تو خود دیکھا تھا کہ وہ جھا نک رہاہے انہوں نے ایک بانس اٹھایا اور پیچھے سے جا کر اس کے سر پر مارا اور وہ گر گیا.جب وہ گرا تو ننگا ہو گیا.حضرت صفیہ ؓ نے حسان بن ثابتؓ سے کہا اب تو جاؤ.حسانؓ نے کہا میں تو نہیں جا سکتا تم خود ہی مارو شاید اس میں کوئی دم باقی ہو حضرت صفیہؓ نے پردہ کیا منہ پر چادر ڈالی اور چونکہ وہ ننگا ہو چکا تھا اس لئے پہلے اس پر کپڑا ڈالا اور پھر اس کے سر کو کچل دیا(البدایۃ و النـھایۃ غزوۃ خندق) جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متواتر ایسی اطلاعات پہنچیں کہ یہودیوں نے مخالفانہ کا رروائی شروع کر دی ہے اور انہوں نے جاسوس بھی بھیجنے شروع کر دیئے ہیں اور شاید جلد حملہ ہو جائے گا تو آپ نے عورتوں کی حفاظت کے لئے پانچ سو کے دو لشکر مقرر کر دیئے جن میں سے ایک دو سو کا تھا اور ایک تین سو کا تھا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے صرف سات سو مسلمان رہ گئے.یہ ایک کمزور طبقہ کی امداد کے لئے کتنی شاندار قربانی تھی جو آپ نے کی کہ فوج کے ایک معتد بہ حصہ کو جس نے شہر کی حفاظت کرنی تھی لشکر سے کاٹ کر عورتوں کی حفاظت کے لئے بھیج دیا.یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ آپ عورتوں کی حفاظت کے لئے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لئے بھی تیار تھے.(۱۸) جنگ بدر کے موقعہ پر بھی آپ نے اپنے خلق عظیم کا ثبوت دیا.حضرت عباسؓ جو ان دنوں مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس جنگ میں شریک تھے.آپ خفیہ طور پر تو مسلمان ہو چکے تھے مگر جب کفار لڑائی کے لئے آنے لگے تو ان کو بھی ساتھ لے آئے.یہ آنے کو تو آ گئے مگر ادھر ادھر وقت ٹلاتے رہے.جب کفار کو شکست ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت عباسؓ کو بھی قید کر لیا اس زمانہ میں ہتھکڑیاں تو تھیں نہیں اور نہ ہی کانٹے دار تار ہوا کرتی تھی.رسیوں سے ہی قیدیوں کو باندھ کر ان کی حفاظت کرتے تھے اور رسیاں ذرا زور سے باندھتے تھے جس سے قیدی کو تکلیف ہوتی تھی صحابہ ؓ کہتے ہیں کچھ دور جا کر ہم نے منزل کی تو ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آتی.ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بات کیاہے.بعض نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حضرت عباس ؓ سے محبت ہے ان کے کراہنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے.اس پر صحابہؓ نے فیصلہ کیا کہ حضرت عباسؓ کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں چنانچہ انہوں نے آہستہ سے جا کر حضرت عباسؓکی رسیاں ڈھیلی کر دیں جب ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں تو انہوں نے کراہنا بند کر دیا.جہاں محبت ہو تی ہے وہاں وہم بھی ہو تا ہے.تھوڑی دیر تک جب حضرت عباس کے کراہنے کی آوا ز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آئی تو آپ نے خیال کیا کہ شاید آپ تکلیف کی وجہ
Page 155
سے بے ہوش ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئے ہیں.آپ گھبرائے اور صحابہؓ کو بلا کر کہا عباسؓکی آواز کیوں نہیں آتی انہوں نے جواب دیا.یارسول اللہ عباسؓکے کراہنے کی آواز آرہی تھی جس سے ہم نے محسوس کیا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس لئے ہم نے عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں.یہ آپ کی مرضی کی بات تھی اور چاہیے تھا کہ آپ خوش ہوتے مگر آپ نے فرمایا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا یا تو سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں اور یا پھر عباسؓکی رسی بھی ڈھیلی نہ کی جائے.تکلیف اٹھائیں تو سب اٹھائیں اور آرام پائیں تو سب پائیں.اگر ایک کو آرام دیا گیاہے تو دوسروں کو بھی یہی آرام ملنا چاہیے.گویا پہلے تو آپ حضرت عباسؓکی تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور جب ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں تو پھر آپ یہ برداشت نہ کر سکے کہ آپ کے چچا کی رسیاں تو ڈھیلی کر دی جائیں اور دوسرے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی نہ کی جائیں.اس طرح آپ نے اپنے عمل سے مساوات اسلامی کا ایک شاندار نمونہ قائم کر دیا.(اسد الغابۃ عباس بن عبد المطلب ) (۱۹) جب فتح مکہ ہوئی اور آپ مکہ میں تشریف لائے تو ایک عجیب نظارہ دیکھنے میں آیا.ابو سفیان کو مکہ کے باہر ہی قید کر لیا گیا تھا لیکن آخر ر سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی کہ مکہ میں جاکر اعلان کر دو کہ جو شخص خانہ کعبہ کے اندر آجائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا.جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا جو بلالؓ کے جھنڈے تلے آجائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا جب صبح کے وقت لشکر مکہ کی طرف چلا تو ابو سفیان نے جو حضرت عباسؓ کے دوست تھے آپ سے کہا کہ مکہ جانے سے پہلے مجھے ذرا اپنے لشکر کا نظارہ تو کرادو.انہوں نے یہ بات مان لی اور ابوسفیان کو ایک جگہ پر بٹھا دیا گیا تاکہ وہ لشکر اچھی طرح دیکھ سکیں.ابو سفیان کے آگے سے جو لشکر بھی گذرتا.وہ کہتا یہ فلاں قوم معلوم ہوتی ہے.حضرت عباسؓ فرماتے ٹھیک ہے اسی طرح جو لشکر نکلتا ابو سفیان پہچان لیتا اور کہتا یہ فلاں قوم ہے یہ فلاں قوم ہے.اتنے میں ایک بڑا لشکر ابو سفیان کے سامنے سے گذرا.ابو سفیان نے حیرت سے پو چھا.عباسؓ یہ کون لوگ ہیں؟انہوں نے بتایا یہ انصارؓ ہیں جو مدینہ کے رہنے والے ہیں.یہ بات انصاری لشکر کے کمانڈر نے جو ایک انصاری ہی تھے سن لی اور انہوں نے جوش میں آکر کہا.تم پوچھتے ہو ہم کون ہیں.ہم انصار ہیں اور تھوڑی دیر میں ہی تم لوگوں کا سر کچلنے کے لئے پہنچ رہے ہیں.ابو سفیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا دوڑا گیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا ہے بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا.جو بلالؓکے جھنڈے تلے آجائے گا اسے بھی معاف کر دیاجائے گا جو
Page 156
خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا.جو گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا اور آپ کے فلاں جر نیل نے کہا ہے کہ ہم تم لوگوں کا سر کچلنے کے لئے جا رہے ہیں.آپ نے فرمایا مکہ والوں کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا.خدا تعالیٰ نے جنہیں عزت دی ہے انہیں کون ذلیل کر سکتا ہے.پھر آپ نے اس کمانڈر کو بلایا اور اسے معزول کر دیا.اس لئے کہ اس نے ابو سفیان کا دل دکھایا ہے اور اس کمانڈر کا بھی لحاظ رکھا کہ اس نے اسلام کی محبت کے جوش میں یہ بات کی تھی اور اسی کے بیٹے کو اس کی جگہ کمانڈر مقرر کر دیا(السیرۃ الحلبیۃ فتح مکۃ) عین حملہ کے وقت ایک کمانڈر کا بدل دینا اس لئے کہ اس نے کسی دشمن کی دل شکنی کی ہے یہ معمولی چیز نہیں.ایسا کرنے سے بسا اوقات لشکر میں بغاوتیں ہو جاتی ہیں مگر آپ نے کوئی پروا نہ کی اور اس نازک موقعہ پر بھی آپ نے اپنے خلق عظیم کا ایسا نمونہ دکھایا جس کی مثال کوئی اور نبی پیش نہیں کر سکتا.(۲۰)فتح مکہ کے موقعہ پر جس عفو و کرم سے آپ نے کام لیا اور اپنے جانی دشمنوں کو لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ کہا.وہ بھی آپ کے اخلاق فاضلہ کی ایک بہترین مثال ہے لیکن اس سلسلہ میں ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی.میں خدا تعالیٰ کے فضل سے علم النفس کا بہت ماہر ہوں.یوں تو میں پرائمری پاس بھی نہیں مگر علم النفس کے ماہر لوگ بھی گفتگو میں مجھ سے خدا تعالیٰ کے فضل سے دبتے ہیں اور وہ سینکڑوں کتابیں پڑھ لینے کے بعد بھی میرے علم النفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.میں نے دیکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم النفس کے لحاظ سے ایک ایسی شاندار مثال ملتی ہے کہ اگر چہ وہ بظاہر چھوٹی سی ہے مگر علم النفس کے ماتحت وہ نہایت عظیم الشان چیزہے اور وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے حضرت بلال کو جھنڈا دیا اور فرمایا جو شخص اس کے جھنڈے تلے آجائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا.علم النفس کے لحاظ سے آپ کے اخلاق فاضلہ کی یہ ایک زبردست مثال ہے ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت بلالؓایک غلام تھے اور غلامی کی حالت میں ان کا آقا ان کو سخت تکالیف اور دکھ دیاکرتا تھا،پتھروں پر گھسیٹتا تھا، گرم ریت پر لٹا تا تھا اور جو تیوں سمیت ان کے سینہ پر چھلانگیں مارتا اور کودتا اور کہتا کہ تم اقرار کرو کہ بتوں میں بھی طاقت ہے مگر وہ ان سب تکالیف کے باوجود یہی کہتے کہ اَسْھَدُ اَنْ لَّا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ خدا تو ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں.حضرت بلال ؓ پر جو ظلم ہوئے تھے اور جو ایذائیں ان کو دی گئیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے یقیناً وہ خیال کرتے ہوں گے کہ جب اسلام کو فتح حاصل ہو گی تو میں ان کفار سے بدلہ لوں گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان بھی میرا بدلہ بڑی سختی سے کفار سے لیں گے.یہ ایک قدرتی بات تھی جو ان کے دل میں پیدا ہوئی ہو گی.لیکن جب فتح مکہ ہوئی اور
Page 157
ابوسفیان نے کہاہم آپ کی قوم ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے.تو آپؐنے فرمایا اچھا جو خانہ کعبہ میں داخل ہوجائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے معاف کر دیاجائے گا اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں گے انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا.اس کے یہ معنے تھے کہ سب کے لئے ہی معافی کا راستہ کھول دیا گیا تھا اور بلالؓکے ولولے اس کے دل ہی میں سڑ جانے والے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دشمنوں کے جذبات کا اتنا خیال کیا اپنے ایک مخلص سپاہی کو کب نظر انداز کر سکتے تھے.آپ نے اوپر کے تین احکام کے ساتھ ایک چوتھا حکم اور دیا کہ میں بلال ؓ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیتا ہوں جو شخص بلالؓ کے جھنڈے تلے آکر کھڑا ہو جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا.اس طرح آپ نے اپنی طرف سے دی گئی معافی کو بلالؓ کی طرف منتقل کر دیا اور معافی کی شکل یہ بنادی کہ میں معاف نہیں کرتا بلال معاف کرتا ہے.اس طرح بلالؓ کا دل ٹھنڈا کر دیا اور اسے یہ فخر بخش دیا کہ اس پر ظلم کرنے والے اس کی پناہ میں آنے اور اس کے معافی دینے سے بخشے جائیں گے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کا بدلہ بھی لے لیا اور مکہ والوں کو معافی بھی دے دی.آپ نے حضرت بلالؓ کا بھی خیال رکھا اور اس کے جذبات کومجروح نہ ہونے دیا اور مکہ والوں کا بھی خیال رکھا اور انہیں معاف فرما دیا گویا اس رنگ کے انتقام کے ذریعہ آپ نے ایک طرف حضرت بلال کا سر اونچا کیا اوردوسری طرف مکہ والوں کو بھی عذاب سے نجات دلوادی.(۲۱) بہادری اور توحید کا مظاہرہ جو آپ نے جنگ حنین کے موقعہ پر کیا اس کی مثال بھی دوسرے انبیاء پیش کرنے سے عاجز ہیں.سینکڑوں تیر انداز دو رویہ کھڑے تھے.اسلامی لشکر تتر بتر ہو چکا تھا اور چار ہزار کے لشکر میں آپ گھر ے ہوئے تھے.ایسی خطر ناک حالت میں آپ نے دشمن کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اکیلے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا.حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے نہ بڑھیں.پہلے پیچھے ہٹ کر لشکر کو اکٹھا کیاجائے اور پھر حملہ کیا جائے مگر آپ نے فرمایا.ابو بکرؓ میرے گھوڑے کی لگام چھوڑ دو.پھر آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑھ لگائی اور با آواز بلند کہا اَنَا النَّبِیُّ لَا کَذِب اَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِب (بخاری کتاب المغازی باب قول اللہ تعالٰی وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ...) میں نبی ہوں.جھوٹا نہیں مگر اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ دشمن کے تیروںاور تلواروں کی پروا نہ کرتے ہوئے میں
Page 158
اکیلا آگے بڑھ رہاہوں تم کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ مجھ میں خدائی صفات آگئی ہیں بلکہ یاد رکھنا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں گویا آپ نے ایک طرف انتہائی دلیری کا اظہار کیا اور دوسری طرف توحید کو قائم رکھا.(۲۲) اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے بہادری اور ایثار کا ایسا شاندار مظاہرہ کیاکہ وہ بھی اپنی مثال آپ ہے.صحابہؓ فرماتے ہیں ہمیں خبریں آرہی تھیں کہ قیصر کی فوجیں آرہی ہیں اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتی تھیں.ہم روزانہ حفاظت کی تدابیر کرتے تھے.ایک رات یک دم شور پڑا اور لوگ گھروں سے باہر بھاگے کچھ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے اور کچھ میدان کی طرف دوڑ پڑے اسی طرح لوگ متفرق طرف دوڑ رہے تھے کہ ہم نے دیکھاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے باہر سے تشریف لا رہے ہیں.آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا میں نے شور سنا تھا اس لئے باہر چلا گیا مگر کوئی خطرہ کی بات نہیں غور کرو آدھی رات کا وقت ہے اور آپ اکیلے باہر نکل جاتے ہیں کسی کو ساتھ نہیں لیتے اور جبکہ صحابہؓ ابھی تجویزیں سوچ رہے تھے کہ ہم کیاکریں،آپ پتہ لگا کر واپس بھی آجاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کوئی خطرہ کی بات نہیں.(بخاری کتاب الادب باب حسن الخلق و السخاء و ما یکرہ من البخل) (۲۳) لوگوں کے حقوق کا آ پ کو اس قدر خیال رہتا تھا کہ ایک دفعہ نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہی آپ گھر کی طرف جلدی جلدی تشریف لے گئے صحابہؓ کہتے ہیں اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھلانگیں مارتے ہوئے ہمارے اوپر سے گذرے.تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے ایک دینار اپنے ہاتھ میں پکڑا ہو اتھا.آپ نے فرمایا غنیمت اور صدقات کا جو مال آیا ہوا تھا وہ ہم تقسیم کر رہے تھے کہ اس میں سے ایک دینار نیچے گر گیا اور یاد نہ رہا کہ کہاں گرا ہے.اب جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو خیال آیا کہ وہ دینار اٹھایا نہیں گیا.چنانچہ میں جلدی جلدی گھر گیا تا کہ بھول نہ جاؤں اور خدا تعالیٰ کے بندوں کا حق ضائع نہ ہو.(بخاری کتاب الزکٰوۃ باب من احب تعجیل الصدقۃ من یومھا) اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام حسنؓابھی تین سال کے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ کی کچھ کھجوریں آئیں.حضرت امام حسنؓدوڑے دوڑے آئے اور ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی.آپ نے دیکھ لیا اور فرمایا تھوکو.وہ ابھی بچے ہی تھے اور کھجور میٹھی تھی بچے میٹھی چیزیں کہاں پھینکتے ہیں.انہوں نے نہ تھو کا.آپ نے زور سے ان کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور کو باہر نکالا اور فرمایا یہ لوگوں کا حق ہے تمہارا نہیں.(بخاری کتاب
Page 159
الزکٰوۃ باب اخذ صدقۃ التـمر عند صرام النخل.....) (۲۴) آپ کے جذبہ احسان مندی کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ آپ نے ایک لشکر لے کر طے قبیلے پر حملہ کیا.انہیں شکست ہوئی اور وہ سب قید ہو گئے.جب وہ قیدی بناکر آپ کے سامنے لائے گئے تو آپ کے سامنے ایک لڑکی پیش ہوئی اس نے آگے بڑھ کر کہا.آپ جانتے ہیں میں کون ہوںرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا.اس لڑکی نے کہا میں اس باپ کی بیٹی ہوں جس کی سخاوت کے ذکر سے سارا عرب گونج رہاہے.وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باپ محسن تھا اور وہ دنیا کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا تھا.ہم ایسے باپ کی لڑکی کو قید کرنا نہیں چاہتے.چنانچہ آپ نے اسے آزاد کر دیا اس لڑکی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں یہ ناپسند کرتی ہوں کہ میں تو آزاد ہو جاؤں اور میرے قبیلے کے سب افراد قید ہوں.آپ نے فرمایا اچھا وہ بھی آزاد ہیں.پھر اس لڑکی نے اپنے بھائی کی سفارش کی جو بھاگا ہو اتھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کو بھی مان لیا(السیرۃ الـحلبیۃ سریۃ علی بن ابی طالب) حاتم طائی کا اسلام پر کوئی احسان نہیں تھا وہ صرف اپنے علاقہ میں سخاوت کے لئے مشہور تھا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کے لئے اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا.اس کی قوم آپ سے لڑی تھی اور لڑائی میں قید ہو کر آئی تھی لیکن آپ نے محض اس وجہ سے کہ وہ غریبوں پر احسان کیا کرتا تھا اس کے سارے قبیلے کو معاف کردیا اور فرمایا ہم ایسے شخص کی قوم کو قید نہیں کر سکتے جو اپنی زندگی میں غریبوں پر احسان کیا کرتا تھا.(۲۵) آپ کی مہمان نوازی کا یہ حال تھا کہ آپ کے پاس ایک دفعہ ایک یہودی آیا اور اس نے کہا میں آپ سے اسلام کی باتیں سننا چاہتا ہوں.آپ نے اسے اپنے ہاں ٹھہرایا اور بڑی خاطر مدارات کی.وہ یہودی ایک دو دن آپ کے پاس رہا اور آپ اسے تبلیغ کرتے رہے ایک دن وہ چپکے سے چلا گیا اور اس کپڑے پر جو اسے فرش پر بچھانے کے لئے دیا گیا تھا پاخانہ پھر گیا(ان دنوں چارپائیوں کا رواج نہ تھا)رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھ کر اس کپڑے کو دھلوایا.ایک عورت جو پانی ڈال رہی تھی اس نے اس یہودی کے متعلق سخت کلامی کی اور کہا خدا تعالیٰ اس شخص کا بیڑا غرق کرے جو اس طرح کپڑے پر پا خانہ کر گیاہے.آپ نے فرمایا ایسی بد دعائیں مت دو تمہیں کیا پتہ ہے کہ اسے کیا تکلیف تھی.شاید اس کے پیٹ میں خلل ہو.(۲۶)آپ بادشاہ ہوئے مگر بادشاہت میں بھی آپ نے غربت کو پسند کیا.چنانچہ ایک دفعہ حضرت فاطمہؓ آپ کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھ دکھائے ان کے ہا تھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے.
Page 160
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سارے کام خود ہی کرتی ہوں، بچوں کو پالتی ہوں،کھانا پکاتی ہوں،چکی پیستی ہوں.آپ مجھے کوئی خادم عنایت فرمائیں تاکہ ان کاموں میں مجھے مدد مل سکے ان دنوں چونکہ کوئی خاص محکمہ قیدی رکھنے کا نہ تھا اس لئے جو قیدی آتے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیئے جاتے تھے.حضرت فاطمہؓ کا اشارہ بھی اسی بات کی طرف تھا کہ مجھے بھی کوئی قیدی دے دیا جائے جو گھر کے کاموں میں میری مدد کر سکے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم کیوں غمگین ہو تم نماز کے بعد ذکر الٰہی کیا کرو.اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہاری ان تکلیفوں کو دور فرمادے گا.اس طرح آپ نے ان کی دلجوئی بھی کر دی اور بادشاہ بن کر بھی غربت کو ہی پسند کیا.(بخاری کتاب النفقات باب عمل المرأۃ فی بیت زوجھا) (۲۷) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بے مثال تقویٰ پایا جاتا تھا اس کا اس امر سے پتہ چل سکتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک دن اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ انسان خواہ کتنا بڑا ہو اس سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں چھوڑتا.میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو جس کی وجہ سے میں خدا تعالیٰ کے سامنے مجرم بنوں.اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے.صحابہؓ کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اس کا اندازہ دوسرے لوگ کہاں کر سکتے ہیں.ان کے تو ہوش اڑ گئے.مگر ایک صحابیؓنہایت اطمینان سے آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک تکلیف پہنچی ہے.ایک دفعہ ایک لڑائی میں آپ صفیں ٹھیک کروارہے تھے میں بھی صف میں کھڑا تھا کہ آپ میرے پیچھے سے آئے اس وقت آپ کی کہنی مجھے لگی تھی.یا رسول اللہ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں.آپ نے فرمایا ہاں لے لو.یہ دیکھ کر دوسرے صحابہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور شاید اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سامنے نہ ہوتے تو وہ اس صحابی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے.مگر اس صحابیؓ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم پر اس وقت کرتہ نہیں تھا آپ کا تو کرتہ ہے.آپ نے فرمایا.اچھا کرتہ اٹھالو.اس نے کرتہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر نہایت ادب اور پیار کے ساتھ اس نے آپ کی پیٹھ پر بوسہ دیا اور پھر اشکبار آنکھوں کے ساتھ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بدلہ کیسا.یہ تو میں نے پیار کرنے کا ایک بہانہ بنایا تھا اور چاہاتھا کہ آپ کی اجازت سے اس طرح فائدہ اٹھالوں شاید مجھے پھر پیار کا موقعہ ملے یا نہ ملے.یہ نظارہ دیکھ کر باقی صحابہؓ جو بہت غصہ میں تھے وہ اس صحابی پر رشک کرنے لگے کہ کاش یہ بہانہ ہمیں بھی سوجھتا اور آج ہم بھی پیار کر لیتے.لیکن آپ کا تقویٰ دیکھو کہ اتنی خدمات کے باوجود آپ نے فرمایا.اگر کوئی ادنیٰ سا بھی دکھ مجھ سے کسی کو پہنچا ہو تو وہ آکر مجھ سے بدلہ لے
Page 161
(۲۷) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو بے مثال تقویٰ پایا جاتا تھا اس کا اس امر سے پتہ چل سکتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک دن اپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ انسان خواہ کتنا بڑا ہو اس سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں چھوڑتا.میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو جس کی وجہ سے میں خدا تعالیٰ کے سامنے مجرم بنوں.اگر تم میں سے کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے.صحابہؓ کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا اس کا اندازہ دوسرے لوگ کہاں کر سکتے ہیں.ان کے تو ہوش اڑ گئے.مگر ایک صحابیؓنہایت اطمینان سے آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے ایک تکلیف پہنچی ہے.ایک دفعہ ایک لڑائی میں آپ صفیں ٹھیک کروارہے تھے میں بھی صف میں کھڑا تھا کہ آپ میرے پیچھے سے آئے اس وقت آپ کی کہنی مجھے لگی تھی.یا رسول اللہ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں.آپ نے فرمایا ہاں لے لو.یہ دیکھ کر دوسرے صحابہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور شاید اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سامنے نہ ہوتے تو وہ اس صحابی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے.مگر اس صحابیؓ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے جسم پر اس وقت کرتہ نہیں تھا آپ کا تو کرتہ ہے.آپ نے فرمایا.اچھا کرتہ اٹھالو.اس نے کرتہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر نہایت ادب اور پیار کے ساتھ اس نے آپ کی پیٹھ پر بوسہ دیا اور پھر اشکبار آنکھوں کے ساتھ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بدلہ کیسا.یہ تو میں نے پیار کرنے کا ایک بہانہ بنایا تھا اور چاہاتھا کہ آپ کی اجازت سے اس طرح فائدہ اٹھالوں شاید مجھے پھر پیار کا موقعہ ملے یا نہ ملے.یہ نظارہ دیکھ کر باقی صحابہؓ جو بہت غصہ میں تھے وہ اس صحابی پر رشک کرنے لگے کہ کاش یہ بہانہ ہمیں بھی سوجھتا اور آج ہم بھی پیار کر لیتے.لیکن آپ کا تقویٰ دیکھو کہ اتنی خدمات کے باوجود آپ نے فرمایا.اگر کوئی ادنیٰ سا بھی دکھ مجھ سے کسی کو پہنچا ہو تو وہ آکر مجھ سے بدلہ لے لے(المعجم الکبیر للطبرانی جلد ۳ صفحہ ۵۹،۶۰) (۲۸) آپ کے انکسار کی یہ حالت تھی کہ آپ اپنے آنے پر لوگوں کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ تو ایرانیوں کا رواج ہے.میں بادشاہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے.(ابو داؤد کتاب الادب باب فی قیام الرجل ) آپ کے انکسار کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ایک دن ایک انصاری بیمار ہو گئے.آپ اس کی تیمار دار ی کے لئے تشریف لے گئے.واپسی پر اس انصاری نے آپ کو سواری کے لئے ایک گھوڑا دیا اور اپنے بیٹے سے کہاکہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤ شاید آپ کو اور آدمی تلاش کرنے میں دقت ہو اور آتی دفعہ گھوڑا واپس لے آناتھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا واپس آگیا.باپ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ میں نے تو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا تھاتا راستہ میں حفاظت بھی ہو جائے اور گھوڑا بھی نہ بدکے اور تم واپس آ گئے ہو.بیٹے نے جواب دیا.میں مجبور تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا تم بھی میرے پیچھے بیٹھ جاؤ.میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے اتنی بے ادبی نہیں ہو سکتی.آپ نے فرمایا پھر مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو سکتا کہ تم پیدل چلو اور میں گھوڑے پر سوار ہوں یا تو تم بھی میرے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوجاؤاور یا پھر واپس چلے جاؤ.چنانچہ میں واپس آگیا.(۲۹) اپنے غریب صحابہؓ سے جو آپ کو محبت تھی اور ان کے احساسات اور جذبات کا آپ جس قدر خیال رکھتے تھے اس کا اندازہ اس امر سے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابیؓ بہت بد صورت تھے.وہ بیچارے مزدور تھے.ایک دفعہ وہ مزدوری کے لئے کہیں کھڑے تھے.پسینہ آیا ہو اتھا اور چہرے پر افسردگی طاری تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم تشریف لائے اور جس طرح بچے آپس میں کھیلا کرتے ہیں آپ نے ان کے پیچھے سے آکران کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے وہ صحابی ؓ بھی سمجھ گئے.وہ جانتے تھے کہ میں غریب ہوں پھر پسینہ آیا ہواہے.مٹی سے میرا جسم لت پت ہے اور ویسے بھی میں بدصورت ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کون ہو گا جو مجھ سے پیار کرے.پھر انہوں نے ہاتھ پھیر کر بھی پہچان لیا تھا کہ یہ رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں.کیونکہ آپ کا جسم بہت ملائم تھا.مگر آپ کی محبت کو دیکھ کر انہیں بھی جوش آگیا اور انہوں نے اپنا جسم آپ کے ساتھ خوب رگڑا.جب آپ ؐ نے دیکھا کہ ان کا دل خوش ہو گیا ہے تو آپؐبول پڑے اور فرمایا ہم ایک غلام بیچتے ہیں اسے کون لے گا.اس صحابیؓ نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے کون خرید سکتا ہے.آپؐنے فرمایا خدا اور اس کے رسول کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے.(مسند احـمد بن حنبل مسند انس بن مالک)
Page 162
ہے.(مسند احـمد بن حنبل مسند انس بن مالک) اسی قسم کا حضرت ابو ہریرہؓ کا واقعہ ہے.حضرت ابو ہریرہ ہمیشہ مسجد میں رہتے تھے تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کریں وہ اس کے سننے سے محروم نہ رہیں چونکہ آپ کوئی کمائی نہیں کرتے تھے اس لئے کچھ دیر تو ان کا بھائی کھانا پہنچاتا رہا.لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب تو ملّاں ہی بن گیا ہے کوئی کام نہیں کرتا تو اس نے کھانا دینا بند کر دیااس وجہ سے بعض دفعہ آپ کو کئی کئی وقت کافاقہ ہو جاتا تھا اور بھو ک کی وجہ سے آپ کی بری حالت ہو جاتی تھی.ایک دن جب آپ کو شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی آپ مسجد کی ایک کھڑکی میں کھڑے ہو گئے اور خیال کیا کہ رستہ سے جو صحابی گذرے گا میں اس سے اس آیت کا مطلب پوچھوں گا جس میں غریبوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے شاید اسے میرا خیال آجائے اور مجھے کھانا کھلادے.اتفاقاً سب سے پہلے حضرت ابو بکرؓ گذرے.حضرت ابو ہریرہؓ نے آپ سے پوچھا قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر:۱۰) اس کا کیا مطلب ہے حضرت ابو بکر ؓ نے فرمایا اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنا کھانا دوسرے کو دے دیتے ہیں.آپ نے یہ جواب دیا اور چلے گئے.پھر حضرت عمرؓ گذرے.حضرت ابو ہریرہؓ نے ان سے بھی یہی سوال کیا.انہوں نے بھی وہی جوا ب دیا جو حضرت ابو بکر ؓ نے دیا تھا اور پھر آگے چلے گئے.حضرت ابو ہریرہ ؓ غصے میں آگئے اور کہنے لگے.یہ کوئی مجھ سے زیادہ قرآن کریم جانتے ہیں.میں نے تو خیال کیا تھا کہ شاید میری شکل دیکھ کر انہیں میر اخیال آجائے گا اور کھانا کھلادیں گے مگر یہ معنے بتاتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں.وہ غصہ میں کھڑے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک پیار کی آوا زآئی.ابو ہریرہ ؓ تم بھوکے ہو! یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی.گویا ابو بکرؓ اور عمرؓ،ابو ہریرہؓ کاچہرہ دیکھ کر بھی یہ نہ پہچان سکے کہ وہ بھوکے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی آواز سے پہچان لیا کہ وہ بھو کے ہیں.حضرت ابو ہریرہؓ پیچھے مڑے اور انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.ابو ہریرہؓ ہم بھی بھو کے تھے مگر ایک دوست نے دودھ کا ایک پیالہ بھیج دیا ہے آؤ ہم دودھ پئیں.ابو ہریرہؓ بہت خوش ہوئے اور آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے.آپ نے فرمایا.ابو ہریرہؓ مسجد میں جاؤ اور دیکھو شاید کچھ اور لوگ بھی بھو کے ہوں اور اگر ایسا ہو تو ان کو بھی ساتھ لے آؤ ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں مجھے یہ سن کر سخت افسوس ہوا کہ ایک پیالہ بھر دودھ ہے اسے بھلا کون کون پئے گا.لیکن چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لئے میں چلا گیا میں نے دیکھا تو مسجد میں میرے جیسے چھ آدمی اور تھے.ان کو بھی میں نے ساتھ لیا اور چل پڑا.مجھے رہ رہ کر افسوس آرہا
Page 163
تھا کہ اب کیا بنے گا.میں نے خیال کیا تھا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے میں خوب پیٹ بھر کر پی لوں گا.مگر اب تو چھ اور بھی حاجت مند مل گئے ہیںدودو گھونٹ ہی حصہ میں آئیں گے خیر ہم آپؐکے پاس چلے گئے.مگر میں نے خیال کیا کہ میں چونکہ بہت بھوکا ہوں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے پہلے پیالہ دیں گے.مگر آپؐنے پیالہ اٹھایا اور ان چھ میں سے ایک کو دے دیا جس سے میری رہی سہی امید بھی جاتی رہی جب وہ آدمی پی چکا تو آپؐنے فرمایا کیا پیٹ بھر گیا ہے.اور پیو.اس نے پھر پیا اور کہا حضور اب تو پیٹ بھر گیا ہے میں اور نہیں پی سکتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس سے لے کر دوسرے شخص کو دےدیا پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کومیں نے خیال کیا اب تو میری خیر نہیں.میرے لئے کیابچے گا.مگر ان چھ آدمیوں کے پی لینے کے بعد بھی جب دودھ کا پیالہ میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ویسا ہی بھر اہوا ہے.کچھ تو ویسے ہی وہ پیالہ بڑا تھا اور پھر انبیاء کی چیزوں میں خدا تعالیٰ بر کت بھی دے دیتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہؓ اب تم پیو.میں نے دودھ پیا اور میرا پیٹ خوب بھر گیا.جب میں پی چکا تو آپؐنے فرمایا.ابو ہریرہ ؓ پھر پیو.میں نے پھر پیا.آپؐنے فرمایا.ابو ہریرہؓ پھر پیو.میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو میری انگلیوں میں سے بھی دودھ نکلنے لگا ہے.پھر آپ نے ہم ساتوں آدمیوں کا جوٹھا خود پیا ( بخاری کتاب الرقاق باب کیف کان عیش النبی و اصحابہ.....) اس واقعہ سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے صحابہؓ کی دلجوئی اور خدمت کا کتنا احساس تھا.(۳۰) شرک کے خلاف آپؐکے دل میں جو جذبہ نفرت پایا جاتا تھا اس کا اس امر سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپؐکی وفات کا وقت قریب آیا.تو حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپؐبے چینی اور اضطراب کے ساتھ بار بار کروٹیں بدلتے اور فرماتے خدا تعالیٰ لعنت کرے یہود اور نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا ہے ( مسلم کتاب المساجد باب النھی عن بناءِ الـمسجد علی القبور) ظاہر ہے کہ آپؐکی مراد صرف یہود اور نصاریٰ کو مطعون کرنا نہیں تھا بلکہ اپنی امت کو توجہ دلا نا تھا کہ مجھے یہ فعل اتنا ناپسند ہے کہ میں مرتے وقت بھی اس پر لعنت بھیج رہا ہوں.یہ نہ ہو کہ تم میری قبر کو بھی ان کی طرح عبادت گاہ بنا لو.حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرب کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں اگر چہ ہزاروں قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئیں.مگر خدا تعالیٰ نے آپ کے مزار مبارک کو ہمیشہ کے لئے شرک سے بچایا.مسلمان عقائد میں بے شک شرک کرنے لگ گئے ہیں.چنانچہ بعض مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں اور بعض آپ کو مُردوں کا زندہ کرنے والا تسلیم کرتے ہیں مگر خدا تعالیٰ نے آپؐکے مقبرہ کو شرک سے ہمیشہ محفوظ رکھاہے.
Page 164
اوپر جو واقعات بیان کئے جا چکے ہیں ان کو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر انفرادی طور پر بھی دیکھا جائے تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت اور برتری میں کوئی شبہ نہیں رہتا اور انسان کو اس حقیقت پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی الحقیقت افضل النبیین تھے.بلکہ میں کہتا ہوں اگر ان امور کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تب بھی ایک چیز تو یقینی طور پر ایسی ہے جو دنیا کے کسی اور نبی کو میسر نہیں آئی اور وہ یہ ہے کہ سوائے آپؐکے کوئی اور وجود تاریخی ہے ہی نہیں.آپؐکی ساری زندگی ایک کھلے ورق کی طرح دنیا کے سامنے ہے.پیدائش سے لے کر وفات تک آپؐکی ساری زندگی کا ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جو دنیا کے سامنے نہ آیا ہو.باقی انبیاء کی زندگی اس طرح تاریخ میں کہاں محفوظ ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں آپ کے گھر کے حالات تو نہیں دیئے گئے کہ آپ کا بیوی کے ساتھ کیسا سلوک تھا، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، ہمسایوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوکنا اور آپ کا پیشاب کرنا اور پاخانہ کرنا تک بھی نہیں چھوڑا گیا.غرض آپ کا کوئی فعل ایسا نہیں خواہ وہ اندرونی ہو یا بیرونی جو چھپا ہوا ہو.آپ کی بیویوں نے حدیثیں بیان کی ہیں جن میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ رات کو کیسے اٹھتے تھے، آپ تہجد کیسے پڑھتے تھے، آپ کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، پھر آپ اپنی بیویوں سے کیسے پیار کرتے تھے.بلکہ انہوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ کے بیویوں کے ساتھ جنسی تعلقات کس رنگ کے تھے.نہاتے تھے تو آپ کس طرح نہاتے تھے.گھر کے متعلق آپ کا کیا رویہ تھا.بچوں کے متعلق آپ کا کیا رویہ تھا.آپ کا کپڑا کیسا تھا، پہننا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، بستر کیسا تھا.غرض آپ کی زندگی کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں اور نہ کوئی لمحہ ایسا ہے جو ہمارے سامنے نہ ہو.دنیا میں اور کون سا نبی ایسا پایا جاتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طرح لوگوں کے سامنے ہو.ایسا کوئی نبی نہیں پایا جاتا.کسی نبی کے موٹے موٹے واقعات لے لینے سے تو اس کی زندگی پاکیزہ ثابت نہیں ہوتی.پاکیزہ زندگی اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب کسی کی ساری زندگی سامنے ہو.اور آپ کے سوا کوئی نبی ایسا نہیں جس کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہو.گویا آپ شیشہ کے ایک مکان میں سے گذر رہے تھے اور ساری دنیا آپ کی طرف جھانک رہی تھی.دو چار گھنٹے تو کوئی ریا سے بھی کام کر سکتا ہے مگر ۲۴ گھنٹے کوئی ریا سے کام نہیں کر سکتا.ایک دن بھی کوئی ریا سے گذار سکتا ہے.مگر یہاں تومہینوں اور سالوں کا سوال ہے جب تک بھی آپ زندہ رہے آپ کی ساری زندگی جس طرح گذری وہ ہمارے سامنے ہے.گھر میں آپ کی بیویاں آپ کی جاسوس تھیں اور وہ بتا دیتی تھیں کہ آپ کس طرح نہاتے تھے،
Page 165
کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پہنتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا، ہمسایوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ تھا، باہر سے آنے والی عورتوں کے ساتھ آپ کا کیسا معاملہ تھا.غرض گھر میں آپ کوئی بھی حرکت کرتے بیویاں اس کو بیان کر دیتیں.آپ باہر تشریف لے جاتے تو وہاں ابو ہریرہ ؓ جیسے صحابی موجود ہوتے جنھوں نے قسمیں کھا رکھی تھیں کہ وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی ہر بات کو یاد رکھیں گے اور دوسروں سے بیان کریں گے.ہر بات جو آپ بیان کرتے ہرحرکت جو آپ کرتے صحابہ اسے یاد کر لیتے اور پھر دوسرے لوگوں سے بیان کرتے.کسی نے آپ سے سوال کیا ہو.آپ نے سختی کی ہو یا نرمی کی ہو.کسی سے کوئی معاملہ کیا ہو.کسی نے آپ سے کوئی چیز مانگی ہو.آپ نے کسی کو کوئی چیز عطا کی ہو.کوئی چندہ لایا ہو.یہ سب واقعات آپ کے صحابہ ؓ نے بیان کر دیئے ہیں.غرض آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی پوشیدہ نہیں.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ۳۳سال زندگی تسلیم کی جاتی ہے.مگر آپ کی ۳۳ سالہ عمر کے واقعات بھی انجیل میں پوری طرح بیان نہیں کئے گئے.درمیان میں کئی کئی مہینوں کا بلکہ کئی کئی سالوں کا خلا آجاتا ہے.اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ایلیاؑ ہیں، سلیمانؑ ہیں، زکریاؑ ہیں اور دوسرے انبیاء ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے یا تورات میں ان کا ذکر آیا ہے.ان میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس کا وجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی طرح تاریخی ہو.پھر ان انبیاء کو لے لو جن کا تورات اور قرآن کریم میں تو ذکر نہیں مگر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت کے مامور اور مرسل تھے.مثلاً کرشن علیہ السلام ہیں، رامچندر علیہ السلام ہیں، بدھ علیہ السلام ہیں، زردشت علیہ السلام ہیں.ان کی بھی ساری زندگی کے حالات ہمیں نہیں ملتے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فعل ہمارے سامنے آگیا ہے جیسے کوئی کوٹ کو پھاڑ کر دکھا دے کہ اس کے اندر کی تہیں بھی ایسی ہیں جیسے اس کے باہر کا حال ہے.خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مزکّٰی تھے اور بوجہ اس کے کہ آپ سب سے بڑے مزکّٰی تھے.آپ سب سے بڑے مزکّٰی بھی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں جس قدر باتوں کا مطالبہ کیا گیا تھا اور جس کی قبولیت کا سورۂ بقرہ میں اعلان کیا گیا تھا اس دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ اس سورۃ کوثر میں فرماتا ہے کہ وہ دعا صرف قبول ہی نہیں ہوئی بلکہ اس شان اور عظمت سے پوری ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی اس سے کوئی نسبت ہی نہیں رہی.گویا اللہ تعالیٰ نے صرف دعائے ابراہیمی کو ہی پورا نہیں کیا بلکہ آپ کو کوثر عطا
Page 166
فرمایا ہے اور ہر چیز آپ کی خواہش اور مطالبہ اور دعا سے بہت بڑھ کر دی ہے.اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِکْ وَ سَلِّمْ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ.میں اوپر بتا چکا ہوں کہ کوثر کے ایک معنے اَلرَّجُلُ الکَثِیْـرُ الْعَطَاءِ وَالْـخَیْـرِ کے بھی ہیں.یعنی ایسا آدمی جو بہت بخشش کرنے والا اور بہت بھلائی والا ہو اور یہ معنے لغت کی کتاب المفردات فی غریب القرآن میں بھی بیان ہوئے ہیں جو مسلمانوں میں سب سے معتبر کتاب لغت قرآن کی سمجھی جاتی ہے.اس کے مؤلف کا نام ابو القاسم الحسین ابن محمد الراغب الاصفہانی ہے.جو عام طور پر امام راغب کہلاتے ہیں اور بعض مورخین ان کو صرف اصفہانی کے نام سے یاد کرتے ہیں.میں اس کتاب کا حوالہ اپنی تفسیر میں کم دیتا ہوں کیونکہ ہماری کتب میں یوروپین لوگوں کے زہریلے اثرات کا دفاع زیادہ مدّ ِنظر ہوتا ہے اور وہ ایسی لغات پر کم یقین رکھتے ہیں جو تفسیری رنگ رکھتی ہیں.اس لئے ان کے خیال سے میں زیادہ تر ایسی لغات کا حوالہ دیتا ہوں جو خالصاً ادبی ہوں اور خصوصاً جن کے مصنف مسیحی ہوں تا یوروپین لوگوں یا مغرب زدہ لوگوں کے لئے محل ِ انکار باقی نہ رہے.مگر چونکہ یہ معنے جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں مسلمانوں سے خاص تعلق رکھتے ہیں میں نے اس لغت کا خاص طور پر حوالہ دیا ہے.یوں یہ معنے اس لغت سے مخصوص نہیں بلکہ اس کے علاوہ تاج العروس وغیرہ بڑی لغت کی کتب میں بھی مذکور ہیں اور ادیب گروہ کی بھی کامل تائید ان کو حاصل ہے.امام راغب فرماتے ہیں اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ.قِیْلَ ھُوَ نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ یَتَشَعَّبُ مِنْہُ الْاَنْـھَارُ.یعنی کوثر جنت کی ایک نہر کو کہتے ہیں جس سے دوسری نہریں نکلتی ہیں وَقِیْلَ بَلْ ھُوَ الْـخَیْـرُ الْعَظِیْمُ اَعْطَاہُ اللہُ الرَّسُوْلَ الْکَرِیْمَ.اور بعض کے نزدیک کوثر وہ خیر عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی.وَقَدْ یُقَالُ لِلرَّجُلِ السَّخِیِّ الْکَوْثَر اور کوثر سخی آدمی کو بھی کہاجاتا ہے.اقرب الموارد نے بھی علاوہ ان معنوں کے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں.یہ معنے بیان کئے ہیں کہ اَلسَّیِّدُ الْکَثِیْرُ الْـخَیْرِ.ایسا سردار جو خیر کثیر والا ہو.اَلرَّجُلُ الْکَثِیْرُ الْعَطَاءِ وَالْـخَیْرِ.ایسا شخص جو بہت سخی ہو اور بڑی خیر والا ہو.گویا نَـھْرٌ فِی الْـجَنَّۃِ اور الْکَثِیْـرُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ کے علاوہ کوثر کے ایک تیسرے معنے بھی ہیں جن کو مفسرین نے بھی تسلیم کیا ہے اور لغت قرآن والوں نے بھی تسلیم کیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ اَلرَّجُلُ الْکَثِیْرُ الْعَطَاءِ وَالْـخَیْـرِ.ایسا آدمی جس میں عطاء و خیر کثرت سے پائی جاتی ہو اور جو انتہا درجہ کا سخی انسا ن ہو.پس اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ کے ایک معنے یہ ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہو گا جو کثیر العطاء و الخیر ہو گا.ان
Page 167
معنوں کی رو سے اس آیت کی یہ صورت ہو گی کہ اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ رَجُلًا کَثِیْرُ الْعَطَاءِ وَالْـخَیْـرِ.ہم تجھے ایک ایسا آدمی دیں گے جس میں عطا و خیر کثرت سے پائی جائے گی.اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ اور فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ کے الفاظ سے جن کی تشریح آگے کی جائے گی.یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کو دیا جائے گا آپ کا روحانی فرزند ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ ایک شخص ظاہر ہونے والا ہے بلکہ وہ فرماتا ہے اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ ہم نے تجھ کو بخشا ہے اورجو کسی کو بخشا جاتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے لحاظ سے دو نام تھے.آپ کا نام احمدؐ بھی تھا اور آپ کا نام محمدؐ بھی تھا اب اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ میں ’’ک‘‘کی جگہ احمد رکھ دو تو آیت یوں بن جائے گی.اِنَّاۤ اَعْطَيْنَا اَحْـمَدَ ہم نے بخشا ہے احمد کو اور چونکہ بخشا جانے والا وجود غلام کہلاتا ہے پس دوسرے لفظوں میں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک غلامِ احمد دنیا میں آئے گا جو کثیر العطاء والخیر ہو گا اس آنے والے وجود کا آپ کے غلاموں میں سے ہونا اوّل تو اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ کے الفاظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ دے دینے کا دو ہی لفظوں میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے.یا تو یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کا صُلبی بیٹا ہو گا اور یا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کا روحانی فرزند یعنی غلام ہو گا.اور چونکہ سورۂ احزاب میں صُلبی بیٹے کی نفی کی گئی ہے اس لئے صرف یہ معنے رہ گئے کہ وہ آپ کا روحانی فرزند یعنی غلام ہوگا.اگلی آیت بھی اسی مفہوم کو واضح کرتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ ہم تجھے غلام احمد بخشنے والے ہیں اس کے نتیجہ میں تو دعائیں کر اور قربانیاں دے.قربانیاں اور دعائیں ہمیشہ بیٹے کی پیدائش پر کی جاتی ہیں.چنانچہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تا ہے تو اسلامی تعلیم کے مطابق اس کا سر مونڈا جاتا ہے، قربانی کا بکرا بطور عقیقہ دیا جاتا ہے اور کچھ صدقہ و خیرات بھی کیا جاتا ہے گویا دعا بھی ہوتی ہے اور قربانی بھی ہوتی ہے.پس فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں کسی روحانی بیٹے کا ذکر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا آدمی ملنے کے یہ معنے ہیں کہ وہ آپ کی روحانی اولاد میں سے ہو گا.صرف ظاہری خادم نہیں ہو گا کیونکہ مادی خادم کے متعلق یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے آقا کے طریق کا بھی پابند ہو جیسے کئی لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ کسی ہندو یا عیسائی کو بھی خادم رکھ لیتے ہیں.پس خادم کے لئے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے آقا کے طریق کا بھی پابند ہو.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللہَ لَیُؤَیِّدُ ھٰذَا الدِّیْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِر (بخاری کتاب الـجھاد والسیر باب اِنَّ اللّٰہَ یُؤَیِّدُ ھٰذَ الدِّیْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِر ) بعض دفعہ ایک فاجر انسان کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید کا کام لے لیتا ہے.مگر اس سے مراد دنیوی تائید ہے دینی تائید نہیں.کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ دینی تائید کے مستحق دینداروں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے اور کسی بے دین کو اس کے لئے چن لے.پس اس امداد سے مراد مالی مدد یا لڑائی
Page 168
وغیرہ میں مدد ہو سکتی ہے دینی مدد نہیں.یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ آنے والا صرف آپ کا خادم نہیں ہو گا بلکہ آپ کی روحانی اولاد میں سے ہو گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے یہ الفاظ بھی رکھ دیئے کہ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ.تو دعائیں کر اور قربانیاں دے.یعنی جس طرح بیٹے کی پیدائش پر شکریہ کے طور پر دعائیں کی جاتی ہیں اور عقیقہ میں قربانی کی جاتی ہے اسی طرح یہ جو تیرا روحانی خادم ظاہر ہونے والا ہے اس کی آمد پر بھی تو خدا تعالیٰ کا شکر یہ ادا کر اور اس کے حضور میں قربانیاں گذار.اس آیت میں ان لوگوں کا بھی ردّ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کی اصلاح کے لئے جس شخص کے آنے کا وعدہ ہے وہ باہر سے آئے گا امت محمدیہ میں سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس شخص کا یہاں ذکر ہے وہ اسی امت میں سے ہو گا باہر سے نہیں آئے گا.مسلمانوں میں یہ غلط خیال پھیل گیا ہے کہ آخری زمانے میں جس آنے والے کی پیشگوئی کی گئی ہے اس سے مراد حضرت مسیح ناصری ؑ ہیں.حالانکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی آنا تھا جو امت موسوی کے ایک فرد تھے.تو پھر اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ اِنَّآ اَعْطَیْنَا مُوْسَی الْکَوْثَر کہنا چاہیے تھا حضرت عیسیٰ ؑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے تھے مگر یہاں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ہم نے تجھے کوثر بخشا ہے.تو دعائیں کر.تو عقیقہ اور قربانیاں کر.اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کوثر سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا ہے کیونکہ عقیقہ اور قربانیاں اور دعائیں اپنے بیٹے کی پیدائش پر کی جاتی ہیں کسی غیر کے بیٹے کے لئے نہیں کی جاتیں.اوپر کے استدلال پر دو اعتراض ہو سکتے ہیں اوّل یہ کہ اگر اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ میں کسی موعود کا ذکر ہے توکیوں نہ سمجھا جائے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی اور ہے یعنی ہم یہ کیوں مانیں کہ اس پیشگوئی میںحضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے کسی اور کا ذکر نہیں.اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پیشگوئی ایک آنے والے مسیح اور مہدی کے متعلق احادیث میں موجود ہے.آپ فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں مسیح اور مہدی پیدا ہو گا جو امت محمدیہ کی اصلاح کرے گا.اب یا تو یہ پیشگوئی ایک شخص کے متعلق ہے یا دو شخصوں کے متعلق ہے جو ایک ہی زمانہ میں آئیں گے.ہمارے نزدیک یہ ایک ہی شخص کے متعلق پیشگوئی ہے جو مسیح بھی ہو گا اور مہدی بھی.اور عام مسلمان اسے دو شخصوں پر چسپاں کرتے ہیں.بہرحال یہ پیشگوئی خواہ ایک فرد کے متعلق ہو جو ہمارے نقطہ نگاہ سے مسیح بھی ہوگا اور مہدی بھی.یا عام مسلمانوں کے نقطہ نگاہ کے مطابق دو شخصوں کے متعلق ہو.جو ایک ہی زمانہ میں
Page 169
ظاہر ہوں گے اور جن میں سے ایک مسیح ہو گا اور دوسرا مہدی.اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی لٹریچر میں اتنی بڑی پیشگوئی اسلامی زمانہ کے کسی اور شخص کی نسبت نہیں اور جب ان کے علاوہ کوئی اور شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیشگوئی کی ہو تو ثابت ہوا کہ جس شخص کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے وہ بھی ان دونوں موعودوں میں سے کوئی ایک ہے اور یا پھر ہمارے عقیدہ کے مطابق وہی شخص ہے جو بیک وقت مہدی بھی ہوگا اور مسیح بھی.ہم یہ نہیں مان سکتے کہ یہ پیشگوئی کسی غیر معروف شخص کے متعلق ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پیشگوئی کو اتنی عظمت دیتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جب سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب اس بڑے فتنے کی خبر دیتے آئے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہو گا(بخاری کتاب الفتن باب ذکر الدجال) اور یہ ایک قدرتی امر ہے کہ جتنا بڑا فتنہ ہو گا اس کو دور کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا انسان ہو گا.بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا زور اس آخری زمانہ میں آنے والے کے متعلق دیا ہے اور احادیث ان پیشگوئیوں سے بھری پڑی ہیں.اگر کوثر سے کوئی غیر معروف آدمی مراد لیاجائے تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ جس شخص کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس کے متعلق خدا تعالیٰ خاموش ہے اور جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے خبر دی اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اور یہ عقل کے خلاف ہے.بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی چیز پر زور دے سکتے تھے جس پر خدا تعالیٰ نے زور دیا اور خدا تعالیٰ بھی اسی خبر کی تائید کر سکتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی.پس کوثر کے لفظ میں جو پیشگوئی ہے وہ اسی کے متعلق سمجھی جاسکتی ہے جسے مسیح اور مہدی کہا گیا ہے.مسیح موعود کے آنے میں موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ میں مشابہت (۲) دوسری دلیل ان معنوں کی تائید میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو سورۃ بقرہ میں آئی ہے اور جس کا یہ جواب ہے.وہ یہ تھی کہ اے اللہ تو اسمٰعیل (علیہ السلام)کی اولاد میں سے ایسا انسان پیدا کر جو یُعَلِّمُھُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ وَیُزَکِّیْھِمْ کا مصداق ہو.یہ دعا جو حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے متعلق کی گئی تھی درحقیقت اس دعا کے مقابل میں تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحٰق علیہ السلام کے متعلق کی تھی اور جس کا بائبل میں ذکر آتا ہے.اس دعا کے طفیل حضرت اسحٰق علیہ السلام کی اولاد میں موسوی سلسلہ چلا جس کی پہلی کڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے.اب ضروری تھا کہ حضرت اسحٰق اور حضرت اسمٰعیل کا توازن قائم رکھنے کے لئے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھی کوئی ایسا انسان ہوتا جو حضرت موسٰی کا جواب ہوتا اور کوئی
Page 170
ایسا انسان ہوتا جو حضرت عیسیٰؑ کا جواب ہوتا.بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور ان سے کئے گئے وعدوں کی بڑی شان کو دیکھتے ہوئے دونوں اسمٰعیلی موعود اپنے مثیلوں سے بڑھ کر ہوتے.چنانچہ اسی امر کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمٰعیل کے خاندان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثیل تھے مگر شان میں ان سے بڑھ کر اور پھر آپ کے ذریعہ سے ایک اور مامور کی خبر دلوائی جو مسیح کا نام پانے والا تھا جس طرح کہ قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا نام دیا گیا تھا اور آپؐ نے اس موعود کے بارہ میں یہاں تک فرمایا کہ کَیْفَ تَـھْلُکُ اُمَّۃٌ اَنَا فِیْ اَوَّلِھَا وَالْمَسِیْحُ اٰخِرُھَا (ابن ماجہ) کہ وہ امت ہلاک نہیں ہوسکتی جس کے شروع میں مَیں ہوں اور جس کے آخر میں مسیح ہو گا.گویا وہی چیز جو حضرت اسحٰق علیہ السلام کی اولاد میں موسوی سلسلہ کو دی گئی تھی وہ آپ کو بھی ملی اور بنو اسمٰعیل اور بنو اسحٰق کے دو سلسلوں میں کامل مشابہت بھی پیدا ہو گئی اور بنو اسمٰعیل کو فضیلت بھی حاصل ہو گئی غرض حضرت اسحٰق علیہ السلام کی اولاد کے بارہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس کے نتیجہ میں موسوی سلسلہ چلا.جس کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی اور خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا.اسی طرح حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولاد کے بارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کے نتیجہ میں محمدی سلسلہ چلا جس کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور آخری زمانہ میں مسیح ثانی یا مسیح موعود کی بعثت کی خبر دی گئی تا مماثلت مکمل ہو جائے.پس اس آیت میں ایک سخی اور بہت بڑی خیر کے مالک غلام یا فرزند روحانی کے دینے کی جو خبر دی گئی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ محمدی سلسلہ کی مشابہت موسوی سلسلہ سے ثابت کرنے کے لئے یہ آخری کڑی زنجیر کی بھی ضرور مکمل ہو کر رہے گی بلکہ موسوی سلسلہ کے نقشِ آخر سے محمدی سلسلہ کا نقش آخر زیادہ نمایاں، زیادہ شاندار اور زیادہ موجبِ مسرت و خوشی اور نیک انجام ہو گا.تیسری دلیل ان معنوں کی تائید میں یہ ہے کہ اس آیت میں ایک مُعطاء یعنی بہت بڑے صدقہ دینے والے اور سخاوت کرنے والے وجود کی پیشگوئی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی ایک ایسے ہی شخص کی خبر دی گئی ہے.ظاہر ہے کہ وہ شخص اور اس آیت میں بیان کردہ شخص ایک ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ پیشگوئی کی علامات اگر مشترک ہوں تو مشارٌ الیہ بھی ایک ہی شخص ہو سکتا ہے جبکہ دونوں پیشگوئیاں ایک ہی سلسلہ اور ایک ہی زمانہ کے متعلق ہوں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے الفاظ یہ ہیں وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ لَیُوْشِکَنَّ اَنْ یَّنْزِلَ فِیْکُمُ ابْنُ مَرْیَمَ حَکَمًا عَدَلًافَیَکْسِـرَ الصَّلِیْبَ وَ یَقْتُلَ الْـخِنْزِیْرَ وَ یَضَعَ الْـجِزْیَۃَ وَ یُفِیْضَ الْمَالَ حَتّٰی لَا یَقْبَلَہُ اَحَدٌ.( بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم )حدیث کے
Page 171
ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے آخری زمانہ میں آنے والے مسیح کے بارہ میں خبر دیتے ہیں کہ وہ اموال لٹائے گا.ان الفاظ کو اور کوثر کے معنوں کو آمنے سامنے رکھو تو دونوں الفاظ بالکل ہم معنے ہیں.’’مال لٹانے والا‘‘اور ’’بے انتہا صدقہ و خیرات کرنے والا‘‘ دونوں الفاظ صاف طور پر ایک ہی وجود پر دلالت کرتے ہیں اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی میں اس شخص کی تعیین بھی کر دی گئی ہے.اس تعیین کو ہم سورۂ کوثر کی پیشگوئی پر چسپاں کرنے پر مجبور ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیین کے مطابق’’کوثر‘‘کی خبر کا مصداق مسیح موعود کو قرار دینے میں نہ صرف حق بجانب ہیں بلکہ اس کے سوا ہمارے لئے اور کوئی چارہ ہی نہیں.کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مہبطِ وحیٔ قرآن ہیں اور آپ سب سے اوّل حقدار ہیں کہ قرآن کریم کے معنے کریں.پس جب آپ نے امت اسلامیہ میں آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والے مسیح کو اموال لٹانے والا وجود قرار دیا ہے تو سورۂ کوثر میں کوثر کے لفظ سے جس بہت سخاوت کرنے والے روحانی فرزند کی خبر دی گئی ہے اس سے بھی مسیح محمدی ہی مراد لیا جائے گا.شاید اس جگہ کوئی سوال کرے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اموال دے اور کوئی قبول نہ کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی پیشگوئی میں تو صرف کوثر کا لفظ ہے یعنی بڑا سخی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بات زائد فرمائی ہے کہ وہ سخی مال لٹائے گا مگر لوگ اسے قبول نہ کریں گے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی پیشگوئی سے بعض لوگوں نے غلط معنے لینے تھے (نادانوں نے نہ کہ عقلمندوں نے)اس لئے ایسے کوتہ اندیشوں کے سمجھانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح زائد کر دی تا سورۂ کوثر کی پیشگوئی کو اس تشریح کے ساتھ ملا کر لوگ ٹھوکر سے بچ جائیں اور وہ اس طرح کہ جن خزانوں کو لوگ ردّ کرتے ہیں وہ روحانی خزانے ہوتے ہیں مادی نہیں.پس اموال کے ردّ کرنے کے الفاظ نے سورہ ٔ کوثر کی تشریح کی ہے کہ اس میں جس بڑے سخی آدمی کی خبر دی گئی ہے وہ سونے چاندی کے سکے نہیں تقسیم کرے گا جن کو لینے سے لوگ عام طور پر انکار نہیں کرتے.بلکہ وہ روحانی خزانے تقسیم کرے گا جن کے قبول کرنے سے اکثر لوگ انکار کیا کرتے ہیں.روحانی علوم اور معارف کو خزانوں یا اموال سے مشابہت دینا قدیم سنت الہامی کتب کی ہے اور انبیاء کا محاورہ ہے.چنانچہ انجیل میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس ان کے دشمن آئے اور کہا کہ روم کا بادشاہ ان سے خراج طلب کرتا ہے وہ اسے دیں یا نہ دیں؟اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا چیز طلب کرتا ہے وہ مجھے دکھاؤ.انہوں نے رومی سکہ دکھایا جس پر رومی قیصر کی تصویر تھی.حضرت مسیحؑ نے کہا کہ یہ تو مال ہی اس کا ہے جو اس کا مال ہے وہ اسے دو اور جو خدا کا مال ہے وہ اسے دو(متی باب ۲۲ آیت ۲۱) اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیحؑ روحانیت اور روحانی علوم کو اموال اور خزانہ
Page 172
سے تشبیہ دیتے تھے اور روحانیت کا مالیہ اپنی قوم سے طلب کرتے تھے مگر ان کی تمثیلی زبان کی وجہ سے ان کے مخالف یہ سمجھتے تھے کہ یہ سرکاری ٹیکس خود طلب کرتا ہے اور حکومت کا مخالف ہے اور اس بات کو پختہ کرنے اور حکومت کا مجرم ثابت کرنے کے لئے وہ ان کے پاس گئے اور اس رنگ میں سوال کیا کہ مالیہ ہم رومی حکومت کو دیں یا آپ کو دیں.حضرت مسیحؑ ان کی شرارت کو سمجھ گئے اور انہوں نے اپنے مالیہ کی تشریح اس طرح کر دی کہ سکہ پر تو رومی قیصر کی تصویر ہے یہ تو ہے ہی اسی کا حق میں اس سکہ کا مطالبہ کس طرح کر سکتا ہوں.میں تو وہ مال طلب کرتا ہوں جس پر آسمانی حکومت کی مہر ہے یعنی میں تو روحانی قربانیوں اور عرفان کا مطالبہ کرتا ہوں.اس تمام واقعہ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام عام طور پر اموال اور سکوں کا لفظ روحانی معنوں میں استعمال کرتے تھے اور یہ ایک بلیغ اور فصیح کلام کی شان ہے کہ جب اس نے مسیح علیہ السلام کے ایک بروز اور مثیل کی خبر دی تو اس نے اس کی خبر دیتے وقت اسی زبان کو استعمال کیا جسے مسیحؑ ناصری خود استعمال کیا کر تے تھے.قرآن کریم میں بھی خزانہ کا لفظ ظاہری دولت کے سوا دوسری اشیاء کے لئے استعمال ہوا ہے چنانچہ سورہ ٔ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآىِٕنَ رَحْمَةِ رَبِّيْۤ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ١ؕ وَ كَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا.(بنی اسـرآءیل:۱۰۱) اس آیت سے پہلے مذہبی امور کا ذکر ہے اور کلامِ الٰہی کے نزول اور بعثت ِ انبیاء پر بحث کی گئی ہے.پس اموال و خزائن میں اوّل نمبر پر کلام الٰہی اور روحانی علوم مراد ہیں.اسی طرح سورہ ٔ طور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق بحث کرتے ہوئے فرماتا ہے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآىِٕنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَۜيْطِرُوْنَ ( الطور:۳) یعنی اپنے انعامات اور روحانی کمالات اور اسرار ِ روحانیہ کا بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے ان کا نہیں.اللہ تعالیٰ نے ان اموال کے ذخیرے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیئے ہوئے.پس یہ کون ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر فائز ہونے پر معترض ہے کیا یہ خدا تعالیٰ کے روحانی خزانوں پر قابض ہیں کہ جس کو یہ چاہیں وہ خزانے دیں گے دوسروں کو نہ مل سکیں گے.محاورۂ انبیاء میں علوم روحانیہ کو اموال سے تشبیہ اوپر کے حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ کتب سماویہ اور محاورہ ٔ انبیاء میں علومِ روحانیہ کو اموال یا خزانہ کہا جاتا ہے اور درحقیقت خزانہ تو ہے ہی وہی.حضرت مسیحؑ نے فرمایا ہے تم روٹی سے زندہ نہیں رہتے جو کھاتے ہو بلکہ تم کلامِ الٰہی سے زندہ رہتے ہو (متی باب ۴آیت ۴) پس کوثر کی پیشگوئی اور مسیحؑ کے خزانہ لٹانے کے اصل معنے یہ ہیں کہ وہ آنے والا علوم و معارف کے خزانے لٹائے گا.مگر لوگ جیسا کہ سب مامورین کے وقتوں میں ہوتا چلا آیا ہے اس کے بھیجے ہوئے خزانوں کو قبول کرنے سے انکار کریں گے.
Page 173
اوپر کوثر کے ایک معنے اَلْـخَیْـرُ الْکَثِیْـر کے بھی بتائے جا چکے ہیں اور خیر کا لفظ اسلام اور دین کے معنوں میں ہی آتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک الہام بھی ہے کہ اَلْـخَیْـرُ کُلُّہٗ فِی الْقُرْاٰنِ.(کشتی نوح ، روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۷) تمام قسم کی خیر اور بھلائی قرآن کریم میں ہی ہے.پس جو شخص قرآنی معارف لٹاتا ہے وہ بالفاظ دیگر خیر تقسیم کرتا ہے.اور یہی کام مسیح موعود کا بتایا گیا تھا.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ قرآنی دولت اس قدر لٹائی کہ جس کا کوئی انتہا نہیں.اس دولت کا انکار غیروں نے تو کرنا ہی تھا خود مسلمانوں نے بھی بد قسمتی سے اس کو لینے سے انکار کر دیا.وہ لوگ جنہوں نے اس دولت کو نہیں لیا وہ اس کی عظمت کو کیا سمجھ سکتے ہیں.ہم لوگ جنہوں نے اس دولت کو قبول کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کی کیا عظمت ہے اور یہ کتنی قیمتی اور بے مثال چیز ہے.ہم نے تو اس دولت سے اس قدر حصہ پایا ہے کہ ہمارے گھر بھر گئے ہیں.مثلاً میرا اپنا وجود ہی ہے.دنیوی لحاظ سے میں پرائمری فیل ہوں.مگر چونکہ گھر کا مدرسہ تھا اس لئے اوپر کی کلاسوں میں مجھے ترقی دے دی جاتی تھی.پھر مڈل میں فیل ہوا مگر گھر کا مدرسہ ہونے کی وجہ سے پھر مجھے ترقی دے دی گئی.آخر میٹرک کے امتحان کا وقت آیا تو میری ساری پڑھائی کی حقیقت کھل گئی اور میں صرف عربی اور اردو میں پاس ہوا اور اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دی گویا میری تعلیم کچھ بھی نہیں.مگر آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے سامنے قرآن کریم کے خلاف کوئی اعتراض کیا ہو اور پھر اسے شرمندگی نہ ہوئی ہو بلکہ اسے ضرور شرمندہ ہونا پڑا ہے اور اب بھی میرا دعویٰ ہے کہ خواہ کوئی کتنا بڑا عالم ہو.وہ اگر قرآن کریم کے خلاف میرے سامنے کوئی اعتراض کرے گا تو اسے ضرور شکست کھانی پڑے گی اور وہ شرمندہ اور لا جواب ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا.میں یوروپ بھی گیا ہوں، میں مصر بھی گیا ہوں، میں شام بھی گیا ہوں اور میں ہندوستان میں بھی مختلف علوم کے ماہرین سے ملتا رہا ہوں مگر ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے علمی اور مذہبی میدان میں خدا تعالیٰ کے فضل سے فتح نہ پائی ہو.بلکہ جب بھی انہوں نے مجھ سے کوئی گفتگو کی ہے انہیں ہمیشہ میری فوقیت اور میرے دلائل کی مضبوطی کو تسلیم کرنا پڑا ہے.ایک دفعہ کچھ لوگ مجھے ملنے کے لئے قادیان گئے.ان میں سے ایک مسٹر لیوکس تھے جو اس وقت فورمین کرسچین کالج کے پرنسپل تھے.بعد میں ہندوستانی طلبا ء نے ان کی مخالفت کی کہ ہمیں انگریز پرنسپل نہیں چاہیے اس لئے ان کی جگہ مسٹر دتہ کو لگا دیا گیا.ان کے ساتھ مسٹر ہیوم بھی تھے جو وائی.ایم.سی.اے کے سیکرٹری تھے اور مسٹر والٹر بھی تھے جو ان کے لٹریری سیکرٹری تھے.میرے سامنے انہوں نے بعض سوالات کئے جن کا میں نے جواب دیا اور ان کو ایسا شرمندہ کیا کہ مسٹر لیوکس نے سیلون میں جا کر ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ عیسائیت اور اسلام
Page 174
کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کا فیصلہ کسی بڑے شہر میں نہیں ہو گا بلکہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہو گا جس کا نام قادیان ہے.میں ابھی چھوٹا سا تھا میری عمر پندرہ سولہ سال کی ہو گی کہ میں نے رؤیا میں دیکھا کہ جیسے کوئی کٹورہ ہو تا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز آکر گرے تو اس میں سے ٹن کی آواز نکلتی ہے اسی طرح اس میں سے ٹن کی آواز آئی.پھر وہ آواز پھیلنی شروع ہوئی.پھر مجسم ہوئی پھر وہ ایک فریم بن گئی پھر اس میں ایک تصویر بنی.پھر وہ تصویر متحرک ہو گئی اور اس میں سے ایک وجود نکل کر میرے سامنے آیا اور اس نے کہا میں خدا تعالیٰ کا فرشتہ ہوں اور میں آپ کو سورہ ٔ فاتحہ کی تفسیر سکھانے کے لئے آیا ہوں.میں نے کہا سکھاؤ.اس نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر مجھے سکھانی شروع کی.جب وہ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ پر پہنچا تو کہنے لگا آج تک جتنی تفسیریں لکھی ہیں وہ اس آیت سے آگے نہیں بڑھیں.کیا میں آپ کو آگے بھی سکھاؤں.میں نے کہاں ہاں.چنانچہ اس نے مجھے اگلی آیات کی بھی تفسیر سکھا دی.میری عمر اس وقت پندرہ سال کی تھی اور اب اس رؤیا پر چوالیس سال گذر گئے ہیں.اس عرصہ ٔ دراز میں جو علوم خدا تعالیٰ نے مجھے سورۃ فاتحہ سے سکھائے ہیں ان کے ذریعہ میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر مذہب کا ردّ اس سورۃ سے کر سکتا ہوں اور پھر میرا دعویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دنیا کی تمام اقتصادی تھیوریوں کا جواب موجود ہے خواہ وہ بالشوزم ہو یا کیپٹل ازم ہو یا کوئی اور ہو.میں نے بچپن کے ایّام میں ہی یہ رؤیا سب لوگوں کو سنا دیا تھا اور انہیں بتا دیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے سورہ ٔ فاتحہ کی تفسیر سکھائی ہے.ایک دفعہ ہم امرتسر گئے.ہمارے سکول کا خالصہ کالج امرتسر سے میچ ہوا جس میں ہم نے خالصہ کالج امرتسر کو شکست دی.ہمارے لڑکے اچھے فٹ بال کھیلنے والے تھے.ویسے تو وہاں احمدیت کی بہت مخالفت تھی مگر ایسے مواقع پر مختلف فرقے اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں.جب ہماری ٹیم سکھوں کے مقابلہ میں جیت گئی تو وہاں کے دوسرے مسلمانوں کو بھی بہت خوشی ہوئی اور انجمن اسلامیہ امرتسر نے ہمیں ایک پارٹی دی میں اس ٹیم میں شامل نہیں تھا.صرف میچ دیکھنے کے لئے ساتھ چلا گیا تھا لیکن تھا طالب علم ہی.پارٹی کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی تقریر کریں.میں نے اس سے پہلے عام مجلس میں کبھی تقریر نہیں کی تھی.مدرسہ میں تقریریں کی تھیں.مگر وہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے اور شہر کے رؤوسا موجود تھے اس لئے میں نے عذر کیا اور کہا کہ اس وقت میں تیار نہیں.انہوں نے کہا کچھ بھی ہو آپ کسی موضوع پر تقریر کردیں.میں نے دعا کی کہ خدایا تُو نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ مجھے سورۃ فاتحہ کی تفسیر سکھائی ہے اور اس کے یہ معنے ہیں کہ مجھے ہمیشہ اس سورۃ کے نئے معنے معلوم ہوتے رہیں
Page 175
گے اور میں اس کا لوگوں میں اظہار کر چکا ہوں.اب امتحان کا وقت ہے.تُو مجھے اپنے فضل سے کوئی ایسا مضمون سمجھا جو اس سے پہلے کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو.اس دعا کے بعد میں نے تقریر شروع کی اور یک دم خدا تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک ایسا مضمون ڈالا جو آج تک کسی تفسیر میں بیان نہیں ہوا.میں نے کہا خدا تعالیٰ ہمیں سورہ ٔ فاتحہ میں ایک دعا سکھاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اے خدا نہ ہم مغضوب بنیں اور نہ ضال بنیں.احادیث سے ثابت ہے کہ مغضوب علیھم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصاریٰ ہیں.پس ہم سے یہ دعا کروائی گئی ہے کہ اے خدا تُو ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے سے بچا.دوسری طرف اس بات پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور پھر یہ ابتدائی سورتوں میں سے ایک ہے.اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تھی اس وقت نہ یہودی آپ کے مخالف تھے نہ عیسائی.آپ کے مخالف صرف مکہ کے مشرکین تھے اور اس وقت آپ کو دعا یہ سکھانی چاہیے تھی کہ اے اللہ ہمیں مشرک نہ بنا.مگر بجائے اس کے قرآن کریم دعا یہ سکھاتا ہے کہ اے اللہ ہمیں یہودی اور عیسائی نہ بنا.اس میں کیا راز ہے اور کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تو ذکر نہ کیا جن کی مخالفت کا مکہ میں شدید زور تھا اور یہود و نصاریٰ کا ذکر کر دیا جو وہاں آٹے میں نمک کے برابر تھے.اس میں یہ راز ہے کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا عالم الغیب خدا جانتا تھا کہ اس کی تقدیر کے ما تحت مکہ کا مذہب ہمیشہ کے لئے تباہ کر دیا جانے والا تھا اور آئندہ زمانہ میں اس کا نام و نشان تک نہ ملنا تھا.پس جو مذہب ہی مٹ جانا تھا اس سے بچنے کی دعا سکھانے کی ضرورت ہی نہ تھی جو مذاہب بچ رہنے تھے اور جن سے روحانی یا مادی رنگ میں اسلام کا ٹکراؤ ہونا تھا ان کے بارہ میں دعا سکھا دی گئی.پس کفار کا ذکر ترک کر کے اس سورۃ میں کفار مکہ کے مذہب کے تباہ ہونے اور یہودیوں اور مسیحیوں کا ذکر کرکے ان دو مذاہب کے قائم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے جسے بعد کے واقعات نے نہایت روشن طور پر ثابت کر دیا ہے.پس اس سورۃ کے ذریعہ سے ابتدائی ایامِ نبوت میں ہی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی کامل تباہی کا اس سورۃ میں اعلان فرما دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ اسلام کا خصوصیت سے مقابلہ یہود اور نصاریٰ سے ہو گا اس لئے انہی کی شرارتوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اس طرح قرآن کریم کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت سورۃ فاتحہ میں مہیا کر دیا گیا.یہ نکتہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میرے دل میں ڈالا اور واقعہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ سے یہ استدلال ایسا عجیب ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی مفسر کا ذہن اس طرف نہیں گیا.اس کے بعد اور بھی سینکڑوں مضامین مجھے سورۃ فاتحہ سے سمجھائے گئے اور میرا دعویٰ ہے کہ اگر مجھ پر کوئی اعتراض کیا جائے اور مجھے اس وقت کوئی اور آیت یاد نہ ہو تو خدا تعالیٰ مجھے اس سورۃ سے ہی اس کا جواب سمجھا دے گا.یہ
Page 176
وہ خزانہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں دیا اور جس سے ہمارے گھر بھر گئے.مگر افسوس کہ دوسرے مسلمان اس دولت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں.چوتھی دلیل ان معنوں کی تائید میں یہ ہے کہ آیۃ الکوثر کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا ہو گا کیونکہ اَعْطَیْنٰکَ کے الفاظ کا مفہوم یہی ہو سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی ایک روحانی بیٹے کی خبر پائی جاتی ہے.چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسیؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے حضرت سلمان فارسی ؓ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا سَلْمَانُ مِنَّا اَھْلَ الْبَیْتِ(المستدرک کتاب معرفۃ الـصحابۃ باب ذکر سلمان الفارسی ) لَوْکَانَ الْاِیْـمَانُ عِنْدَ الثُّرَیَّا لَنَالَہٗ رِجَالٌ اَوْ رَجُلٌ مِّنْ ھٰؤُلَآءِ (بخاری کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ )یعنی سلمان ہمارے اہلِ بیت سے ہے اگر کسی وقت ایمان ثریا تک اڑ گیا تو اس کے خاندان کے لوگ اسے وہاں سے واپس لے آئیں گے.ظاہر ہے کہ سلمان ؓ ایرانی النسل تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے نہ تھے.ان کو اولاد میں سے قرار دینا روحانی رشتہ کی طرف ہی اشارہ کرتا ہے پھر آپ کا یہ کہنا کہ اس کی نسل یا خاندان کے لوگ ایمان کو آسمان سے واپس لے آئیں گے.اس کے یہی معنے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اہل فارس میں سے ایک یا بعض وجود ایسا کام کریں گے.چونکہ ایمان کے اٹھنے کا زمانہ احادیث سے مسیح اور مہدی کا زمانہ معلوم ہوتا ہے(مسلم کتاب الفتن باب فی خروج الدجال.....) اس حدیث سے ظاہر ہے کہ یہ فارسی الاصل ایمان لانے والا شخص مہدی آخر زمان ہو گا اور آیت کوثر میں مہدی ہی کی خبر دی گئی ہے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروحانی بیٹا قرار دیا گیا ہے.مسیح اور مہدی ایک ہی شخص ہے اگر کہا جائے کہ یہ پیشگوئی تو زیادہ سے زیادہ مہدی کی نسبت ثابت ہوتی ہے اور آپ آیت کوثر کو مسیح موعود پر چسپاں کر تے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے کہ لَا الْمَھْدِیُّ اِلَّا عِیْسٰی (ابن ماجہ کتاب الفتن باب شدۃ الزمان ) یعنی مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخص کے دو نام ہیں.یہ دو الگ الگ وجود نہیں اور کوثر کا لفظ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ہی وجود ہو گا.یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ہم نے تجھے ایک وجود عطا کیا ہے.اگر دو الگ الگ وجود ہوتے تو اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ کی بجائے اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَیْنِ فرمانا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے تجھے دو وجود جو کوثر ہیں عطا کئے ہیں.غرض ابن ماجہ کی روایت اور قرآن کریم کی یہ آیت دونوں کو ایک ثابت کرتی ہیں.دوسرے معطاء کا لفظ
Page 177
جس کے معنے بڑے سخی کے ہیں مہدی کی نسبت نہیں مسیح کی نسبت ہے.پس جب قرآنی پیشگوئی میں معطاء کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند کو دیا گیا اور سخاوت کی پیشگوئی حدیث میں مسیح کی نسبت ہے تو ثابت ہوا کہ آنے والا ایک ہی شخص ہے.دو نہیں.تیسرے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوگا.مگر موسوی مسیح آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا وہ تو موسوی سلسلہ سے تعلق رکھتا ہے.اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنے والا آسمان سے نہیں آئے گا اور جب مسیح نے بھی زمین سے ہی آنا ہے تو اسے دوسرا وجود قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں.چوتھے حدیث میں مہدی کو بھی آسمان سے آنے والا کہا گیا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَنَالَہٗ رَجُلٌ مِّنْ فَارِس اس وقت دین کو ایک فارسی الاصل آدمی آسمان سے واپس لائے گا اور یہ پیشگوئی مہدی کے متعلق ہے.جب مہدی کو بھی اسلام نے آسمان سے آنے والا قرار دیا ہے تو پھر دو وجود قرار دینے کی کیا ضرورت ہے.آسمان سے آنے ہی نے ساری مشکل پیدا کی تھی.جب مہدی کی نسبت بھی آسمان پر جانا اور پھر وہاں سے ایمان کو واپس لانا ثابت ہوا تو پھر مسیح بھی اسی کو کہیں گے.ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو کہ یہاں کوثر سے مراد سُنّیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت ابو بکر ؓ یا شیعوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت علی ؓ کیوں نہیں ہو سکتے.اسے مسیح اور مہدی پر ہی کیوں چسپاں کیا جاتا ہے؟تو اس کا جواب یہ ہے کہ (۱)یہاں آنے والے کے متعلق معطاء کا لفظ آتا ہے جس کے معنے بہت دینے والے کے ہیں اور یہ نام ان دونوں کو نہیں مل سکتا.حضرت ابو بکر ؓ کے زمانہ میں فتوحات تو شروع ہو گئی تھیں مگر دولت نہیں آئی تھی.دولت حضرت عمر ؓ کے زمانہ میں آئی تھی.اس لئے معطاء کا لفظ حضرت ابو بکر ؓ پر چسپاں ہی نہیں ہو سکتا.باقی رہے حضرت عمر ؓ سو ان کو کوئی بھی حضرت ابو بکر ؓ سے بڑا نہیں سمجھتا.اس لئے یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ ممکن ہے معطاء حضرت عمر ؓ ہی ہوں.پھر حضرت علی ؓ کو بھی معطاء نہیں کہا جا سکتا.اس لئے کہ حضرت علی ؓ کے زمانہ میں بجائے اور دولت آنے کے مسلمانوں کی پہلی دولت بھی جاتی رہی تھی.تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانہ میں شام اور مصر نے بغاوت کر دی تھی اور یہ دونوں نہایت مالدار علاقے تھے اور انہی کی وجہ سے دولت آتی تھی.چونکہ یہ مالدار علاقے ان کے قبضہ سے نکل گئے اس لئے حجاز کی ضروریات بھی انہیں بڑی مشکل سے پورا کرنی پڑتی تھیں.پس حضرت علی ؓ بھی معطاء نہیں کہلا سکتے.دولت صرف حضرت عمر ؓ اور حضرت عثمان ؓ کے زمانہ میں آئی تھی.لیکن ان کو سب سے بڑا نہ سُنّی کہتے ہیں نہ شیعہ.علاوہ ازیں اس پیشگوئی کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ پیشگوئی عالمِ اسلام کے بعد ازآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ وجود متفقہ عقیدہ کے مطابق
Page 178
مسیح اور مہدی کا ہے.مسیح اور مہدی کا ہی وہ زمانہ ہے کہ جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ معلوم اس زمانہ کے لوگ اچھے ہیں یا میرے زمانہ کے.اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہو گا اور اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہو گا یعنی اس کا مجھ سے کامل اتحاد ہو گا.اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسیح میری قبر میں دفن ہوگا( مشکٰوۃ کتاب الفتن الفصل الثالث) مسلمان اس کے معنے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر آپ کی قبر میں دفن ہو گا حالانکہ یہ معنے بالبداہت باطل ہیں وہ کون بے حیا انسان ہو گا جو پھاوڑا لے کر کھڑا ہوجائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودے گا تاکسی اور کو اس میں دفن کرے.کیا اس پر بجلی نہیں گرے گی؟ درحقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام استعارہ کا رنگ رکھتا تھا اور آپ کی مراد یہ تھی کہ اس کا وجود اور میرا وجود کوئی الگ الگ چیز نہیں.اسے اللہ تعالیٰ میرے پاس جگہ عنایت فرمائے گا.مگر بعض مسلمانوں نے اپنی نالائقی سے اس کے یہ معنے کرنے شروع کر دیئے کہ نعوذباللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھودا جائے گا اور اس میں مسیحؑ کو دفن کیا جائے گا.وہ معنے جو میں نے کئے ہیں قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ (الطور:۲۲) یعنی جن لوگوں کی اولاد پاک ہو گی ان کی اولاد کو بھی اپنے والدین کے پاس رکھا جائے گا.یہی مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ آنے والا آپ کا روحانی بیٹا ہو گا اور اس کو آپ کے روحانی مقام کے پاس رکھا جائے گا.اولاد کا باپ کے پاس ہونا انسان کے لئے راحت اور خوشی کاموجب ہوتا ہے خواہ وہ اس درجہ کی ہو یا نہ ہو.اسی طرح قرآن کریم میں آنے والے کانام طارق رکھا گیا ہے اور طارق اسے کہتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں آئے.یعنی وہ گمراہی اور تاریکی کے زمانہ میں آئے گا.حضرت ابو بکر ؓ اور حضرت علی ؓ تو روشنی کی حالت میں آئے تھے وہ اس کے کس طرح مصداق ہو سکتے ہیں.غرض اس پیشگوئی کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالمِ اسلام کے سب سے بڑے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اُمت محمدیہ میں ظاہر ہونے والا تھا.تبھی تو اس کا نام کوثر رکھا گیا.یعنی اس کا وجود اُمت محمدیہ کو دوسرے انبیاء کے سلسلوں پر فضیلت دے گا اور اس کی آمد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کوثریت کا مقام بخشے گا.یعنی آپ کی اُمت کو دوسری اُمتوں پر برتری بخش دے گا.حقیقت یہ ہے کہ جب تک اُمت محمدیہ میں کوئی ایسا وجود نہ ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کرتے ہوئے باقی تمام رسولوں سے افضل ہو اس وقت تک اُمّت محمدیہ دوسری اُمتوں سے افضل ثابت نہیں
Page 179
ہوسکتی.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ آپ سب سے بڑے رسول ہیں مگر بڑے آدمی کی اولاد ضروری تو نہیں کہ بڑی ہو.حضرت سلیمان علیہ السلام کا لڑکا ایک عظیم الشان باپ کی اولاد میں سے تھا مگر خراب نکلا.پس یہ ضروری نہیں کہ اولاد ہمیشہ اپنے باپ جیسی ہو.اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت دوسری اُمتوں سے اسی وقت افضل ثابت ہو سکتی ہے جب اس میں کوئی ایسا فرد پیدا ہو جائے جو آپ کا اُمتی ہوتے ہوئے دوسرے تمام انبیاء سے افضل ہو اور جب کوئی ایسا آدمی پیدا ہو جائے گا تو خود بخود آپ کی امت بھی افضل ثابت ہو جائے گی.غرض ان آخری معنوں کے رُو سے اس آیت میں مسیح اور مہدی کی جو ایک ہی وجود ہیں پیشگوئی کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایک روحانی بیٹا عطا کرنے والے ہیں جس کے پیدا ہونے پر آپ کی امت دوسرے انبیاء کی امتوں پر فضیلت پا جائے گی.کیونکہ وہ بیٹا آپ کی امت سے ہو گا اور پہلے لوگوں سے افضل.پس اس کی افضیلت سے آپ کی اُمت کو فضیلت ملے گی.یہی وہ نکتہ ہے جس کی وجہ سے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ کَانَ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی حَیَّیْنِ لَمَا وَسِعَھُمَا اِلَّا اتِّبَاعِیْ.اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت کرتے.اعتراض کرنے والے کہہ سکتے تھے کہ ان الفاظ میں یوں ہی ایک دعویٰ کر دیا گیا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ ؑ بھی.اب یہ کیونکر پتہ لگے کہ اگر وہ دونوں زندہ ہوتے تو آپ کی اطاعت کرتے.زندہ شخص کے ساتھ تو مقابلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مرنے والے کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اور کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ درست ہے.یہ سوال اس حدیث کے متعلق طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے اور اس کا حل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا شخص ہو جو اپنے آپ کو آپؐکا غلام کہے اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام سے افضلیت کا دعویٰ کرے.پھر بے شک یہ ثابت ہو جائے گا کہ چونکہ آپ کی امت میں سے ایک ایسا آدمی پیدا ہو گیا ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام سے افضل ہے اور پھر وہ آپ کا غلام ہے.اس لئے اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام واقعہ میں زندہ ہوتے تو وہ بھی آپ کے غلام ہی ہوتے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کہ لَوْ کَانَ مُوْسٰی وَ عِیْسٰی حَیَّیْنِ لَمَا وَسِعَھُمَا اِلَّا اتِّبَاعِی ہمارے عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام سے افضل ہوں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام ہوں.مسلمان کہتے ہیں
Page 180
کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ لکھ کر حضرت مسیحؑ کی توہین کی ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلامِ احمد ہے حالانکہ یہ توہین نہیں بلکہ اس حدیث کی تشریح ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام دونوں زندہ ہوتے تو ان کو میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں؎ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلامِ احمد ہے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں لیکن مجھے حضرت عیسٰی علیہ السلام پر فضیلت حاصل ہے اس دعویٰ سے نتیجہ نکلا کہ جب وہ شخص جو حضرت مسیح ناصری ؑ سے افضل ہے وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ کیوں نہ آپ کے غلام ہوتے.اسی طرح اگر ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو کر پھر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں تو یہ لازمی بات ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہوتے تو وہ بھی آپ کے غلام ہوتے.پس مسیح موعودؑ کا ایک ایک دعویٰ قرآنی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے عین مطابق ہے اور آپ ہی وہ وجود ہیں جن کی اَعْطَیْنٰکَ الْکَوْثَرمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی.اس جگہ ایک یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور اَعْطَیْنٰکَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا اس وقت مل چکا تھا پھر اس سے حضرت مرزا صاحب کس طرح مراد ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز یقینی طور پرملنے والی ہو اس کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے.مثلاً اگر ہم کسی کو کہیں کہ میں یہ چیز تمہیں ضرور دوں گا اور وہ کہے کہ آخر کب ملے گی توہم کہتے ہیں سمجھ لو کہ گویا مل گئی.اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اس خبر کے یقینی ہونے پر زور دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ کوثر ہم تمہیں ضرور دیں گے اور اسے ایسی پکی بات سمجھو کہ گویا یہ چیز تمہیں مل گئی ہے.اگر کوئی کہے کہ میں یہ معنے ماننے کے لئے تیار نہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ تم جو کوثر کے معنے جنت کی نہر کے کرتے ہو تو کیا یہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکی تھی؟ یہ کوثر بھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں نہیں ملی تھی.اگر کہو کہ خدا تعالیٰ نے دے دی تھی گو اس کا قبضہ بعد میں وفات پرملے گا تو ہمارا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر نے بھی یہ بیٹا آپ کو دے دیا تھا گو اس کا ظہور آخری زمانہ میں ہونا تھا.اسی طرح بعض لوگوں نے کوثر سے مراد قرآن کریم کی برکات لی ہیں.اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سورۃ نازل
Page 181
ہوئی تھی کیا اس وقت قرآن کریم کی تمام برکات آپ کو حاصل ہو گئی تھیں؟ یہ سورۃ تو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی تھی اور اس وقت قرآن کریم ابھی پورے طور پر نازل ہی نہیں ہوا تھا.پھر اس کی برکات آپ کو کیسے حاصل ہوگئیں.اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ چونکہ یہ قطعی بات تھی اور آپ کو قرآن کریم کے برکات ضرور ملنے تھے اس لئے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ برکات تمہیں ضرور ملیں گی یا دوسرے لفظوں میں تم یہ سمجھ لو کہ یہ برکات گویا تمہیں مل گئی ہیں.اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اَعْطَیْنٰکَ کے الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لڑکا اس وقت آپؐکو مل چکا تھا بلکہ چونکہ اس کا ظہور آخری زمانہ میں یقینی طور پر مقدر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور بتایا کہ خدا تعالیٰ کی ازلی مشیّت نے یہ روحانی فرزند آپ کو دے ہی دیا ہے گو اس کا ظہور ایک وقت کے بعد مقدر ہے.فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْؕ۰۰۳ سو تُو (اس کے شکریہ میں )اپنے رب کی (کثرت سے )عبادت کر اور اسی کی خاطر قربانیاں کر.حلّ لُغات.صَلٰوۃ کے معنے نماز کے بھی ہوتے ہیں اور دعا کے بھی.(اقرب) فَصَلِّ.فَصَلِّ میں جو’ ’فا‘‘ہے یہ عربی زبان میں عطف یعنی اور کے معنوں میں بھی آتی ہے اور عاقبت یعنی’ ’سو اس لئے‘ ‘کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے.جب اور کے معنوں میں آئے تو بالعموم اس میں ترتیب مدّ ِنظر ہوتی ہے(مغنی اللبیب) یعنی اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ’ ’فا‘‘ کے بعد جو کام ہوا ہے وہ پہلے بیان کردہ فعل کے بعد ہوا ہے.اس جگہ’ ’فا‘‘ عاقبت کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے اور مراد یہ ہے کہ ہم نے تجھے کوثر بخشا ہے اس لئے تو نمازیں پڑھ اور قربانیاں دے.یا دعائیں کر اور قربانیاں پیش کر.اِنْـحَرْ نَـحَرَ کے کئی معنے ہوتے ہیں.کہتے ہیں (۱)نَـحَرَ الصَّلٰوۃَ.اور اس کے معنے صَلَّاھَا فِیْ اَوَّلِ وَقْتِـھَا(اقرب) کے ہوتے ہیں یعنی اس نے نماز اوّل وقت میں ادا کی.ہر نماز کے دو وقت ہوتے ہیں.ایک ابتدائی اور ایک انتہائی.مثلاً ظہر کی نماز ہے.زوال سے چند منٹ بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک سایہ سوا گُنا نہ ہوجائے.پھر وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک دھوپ زرد نہیں ہو جاتی.پھر سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو تا ہے اور اس
Page 182
وقت تک چلا جاتا ہے جب تک شفق کی روشنی غائب نہیں ہو جاتی.پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے بعض کے نزدیک اس کا وقت ساڑھے بارہ بجے تک رہتا ہے اور بعض کے نزدیک عشاء کا وقت صبح کی نماز تک رہتا ہے.پھر پَو پھٹنے کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس وقت تک چلا جاتا ہے جب تک کہ سورج نہ نکلے.پس ہر نماز کا کچھ ابتدائی وقت ہوتا ہے اور کچھ آخری وقت ہوتا ہے.نماز کا اصل وقت فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا نماز کا حقیقی وقت ابتدائی اور انتہائی اوقات کے درمیان چکر کھاتا ہے یا اوّل وقت حقیقی ہوتا ہے اور بعد میں نماز کی قضاء چلتی ہے.بعض فقہاء کے نزدیک پہلا وقت ہی اصل وقت ہے اور پھر جتنی دیر ہو گی قضاء چلے گی.لیکن جب دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو پھر قضاء بھی نہیں ہو گی اور بعض فقہاء کے نزدیک پہلے وقت میں نماز پڑھ لینا بہتر ہے مگر اس کا ابتدائی وقت اصل نہیں.یعنی اگر انسان ابتدائی وقت میں نماز پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اگر آخری وقت میں پڑھے تو یہ جائز ہو گا قضاء نہیں ہو گی.وہ فقہاء جن کے نزدیک نماز کا اصل وقت ابتدائی ہے اور بعد میں نماز کی قضاء پڑھی جاتی ہے ان کے نزدیک نماز کے ابتدائی پندرہ منٹ جس میں وہ خیال کرتے ہیں کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر گذر جائیں اور کوئی شخص فوت ہو جائے اس صورت میں کہ اس نے اپنی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ تارک نماز ہو گا کیونکہ اسے موقعہ ملا اور اس نے نماز نہ پڑھی اس لئے وہ گناہ گار ہے.لیکن وہ فقہاء جو اس بات کے حق میں ہیں کہ آخری وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وقت لمبا تھا اور وہ ایسی حالت میں فوت ہوا جبکہ نماز کا وقت ابھی باقی تھا اس لئے وہ گناہ گار نہیں ہو گا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سارے وقت کو ہی نماز کا وقت قرار دیا ہے.چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ دیدہ و دانستہ نماز کو آخری وقت میں ادا کیا(ترمذی کتاب الصلٰوۃ باب ماجاء فی مواقیت الصلٰوۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم) اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی صحابی آپ کی مجلس سے اٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دیتا.اس لئے کہ نماز میں دیر ہو رہی ہے.اسے بہر حال انتظار کرنا پڑتا تھا پس اگر یہ بات درست ہوتی کہ اگر کوئی شخص اوّل وقت یعنی نماز کے ابتدائی چند منٹ گذرنے کے بعد فوت ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکے تو وہ گناہ گار ہے.تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اگر کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا اور وہ اوّل وقت میں نماز نہ پڑھ سکتا تو وہ گناہ گار ہوتا اور گناہ گار بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی وجہ سے ہوتا اور یہ عقل کے خلاف ہے.پس درحقیقت نماز کا سارا وقت ہی اصلی ہوتا ہے.اگر کوئی وقت کو پیچھے کرتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں.ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے وقت میں نماز پڑھنے میں زیادہ برکت ہوتی ہے.پس
Page 183
فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ کے یہ معنے ہوئے کہ تُو اپنے رب کے حضور نماز پڑھ اور اوّل وقت میں پڑھ.(۲)دوسرے معنے نَـحَرَ کے یہ ہیں کہ وَضَعَ یَـمِیْنَہُ عَلٰی شِـمَالِہٖ.اس نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا.یعنی نماز پڑھتے ہوئے جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس کو نحر کہتے ہیں.چاہے وہابیوں کی طرح اوپر باندھے جائیں یا حنفیوں کی طرح نیچے باندھے جائیں.بہر حال دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنے والا نحر کرنے والا کہلائے گا اور اس آیت کے یہ معنے کئے جائیں گے کہ تُو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھ.(۳)تیسرے معنے نحر کے گردن سے نیچے اور سینہ سے اوپر کے حصہ کے ہیں اور وَانْحَرْکے معنے ہوں گے تو سینہ کے اوپر کے حصہ کو چھویا اس کے پاس ہاتھ رکھ.بعض محدثین اس کے یہ معنے کرتے ہیں کہ جو طریقہ محدثین میں نماز کے وقت ہاتھ رکھنے کا ہے وہی درست ہے مگر اس قسم کے استدلال بہت بودے اور کچے ہوتے ہیں.اگر چہ ہم لوگ بھی اہل حدیث کی طرح نماز کے وقت سینہ پر ہاتھ رکھتے ہیں مگر اس وجہ سے کہ اکثر احادیث سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر تعامل سے یہ بات ثابت ہے (ابوداؤد کتاب الصلٰوۃ باب وضع الیـمنٰی علی الیـسـرٰی فی الصلٰوۃ) اس لئے نہیں کہ اس آیت سے یہ مضمون نکلتا ہے.اس قسم کے استدلال ایک سچے امر کو تقویت نہیں پہنچاتے بلکہ مضحکہ خیز بنا دیتے ہیں.(۴)ایک معنے نحر کے یہ ہیں کہ اِنْتَصَبَ بِنَحْرِہٖ اِزَاءَ الْقِبْلَۃِ.وہ قبلہ رُو ہو کر کھڑا ہو گیا.(۵)پانچویں معنے اس لفظ کے یہ ہیں کہ اِنْتَصَبَ وَ نَـھَدَ صَدْرَہٗ.وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے سینہ کو تان لیا.یعنی اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور ادھر اُدھر نہ دیکھا.ان مختلف معنوں کے رُو سے فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ کے معنے ہوں گے تو اپنے رب کے لئے جو ہمیشہ احسان کرتا ہے نماز پڑھ.اوّل وقت میں پڑھ.ہاتھ باندھ کر پڑھ.قبلہ رو ہو کر پڑھ اور ادھر اُدھر نہ دیکھ یا تُو اپنے رب سے یقین، وثوق اور اعتماد کے ساتھ دعائیں کر.اوپر کے معنوں کے علاوہ نحر کے معنے اونٹ کی قربانی کے بھی ہیں.یہ معنے اس لئے ہیں کہ اونٹ کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے منحر یعنی زیرین گردن میں نیزہ مارتے ہیں جس سے اس کی شاہ رگ سے یک دم خون نکلتا ہے اور اونٹ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے.اس کے بعد اسے ذبح کر لیا جاتا ہے اور چونکہ یہ لفظ اونٹ یا اونٹ جیسے بڑے جانوروں کی قربانی کے لئے بولا جاتا ہے.مثلاً زیبرا ہے اس کا بھی اونٹ پر قیاس کر کے نحر کیا جائے گا.لیکن بکرے اور گائے اور اسی قسم کے چھوٹے جانوروں کی قربانی کے لئے نحر کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا.اس لئے اِنْـحَرْ کے معنے یہ ہوں گے کہ تُو بڑی قربانی کر.تفسیر.فَصَلِّ لِرَبِّکَ میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز یعنی اظہار ِ اطاعت یا دعا یعنی طلب حاجات
Page 184
یہ دونوں چیزیں ایسی ہستیوں سے وابستہ ہیں جو مقتدر ہوں مثلاً ایک فقیر کسی اجنبی علاقہ میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ فلاں مکان شاندار ہے.دروازے پر چند ملازم بھی کھڑے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مالک صاحب مقدرت ہے اور وہ یہ سمجھ کر اس دروازہ پر جاتا ہے کہ مجھے یہاں سے کچھ مل جائے گا بعض دفعہ وہ مالک کچھ نہیں دیتا او رپاس ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہوتی ہے وہ بالکل غریب اور کنگال ہوتی ہے لیکن اس کے دل میں رحم ہوتا ہے.وہ اس فقیر کو دیکھتی ہے تو اسے آواز دیتی ہے کہ اِدھر آؤ اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کوئی بچی کھچی روٹی یا کچھ آٹا اس کی جھولی میں ڈال دیتی ہے.لیکن عدمِ علم کی وجہ سے وہ پہلے اس سے نہیں مانگتا.وہ پہلے ایسے شخص سے ہی مانگتا ہے جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ وہ دے سکتا ہے.گویا وہ اندھیرے میں ایک تیر چلاتا ہے اور بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا مگر یہ کہ ضرور ملے گا اس کا اسے علم نہیں ہوتا.لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ مجھے یہاں سے اکثر کچھ نہ کچھ ملا کرتا ہے تو جب وہ آواز دے گا اسے یقین، وثوق اور اعتماد بھی ہو گا اور وہ سمجھے گا کہ میں خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا.فَصَلِّ لِرَبِّکَ میں اللہ تعالیٰ اعتماد پیدا کرنے کے لئے فرماتا ہے کہ تُو اپنے ’’رب‘‘کی عبادت کر یا اپنے ’’رب‘‘کے حضور دعا کر.یہاں رب کا لفظ استعمال کر کے بتایا کہ وہ خدا ایسا ہے جو تمہاری تربیت کرتا ہے.تمہاری ربوبیت کرتا ہے اور تمہیں ترقی دیتا ہے اس طرح رب کا لفظ استعمال کر کے دعا کرنے والے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ جس خدا سے تم مانگنے لگے ہو وہ نہ صرف صاحب ِ مقدرت ہے اور تم جو کچھ مانگو وہ تمہیں دے سکتا ہے.بلکہ وہ سابق زمانہ سے تمہارا مربی و محسن چلا آیا ہے اور ہمیشہ اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے.مگر یہاں پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ سخی بھی تو سب کو نہیں دیتے صرف کسی کسی کو دیتے ہیں.ان کے ہمسایہ میں کئی غریب ہوتے ہیں مگر ان میں سے کوئی کوئی ہی ہوتا ہے جس کی ضروریات کا وہ خیال رکھتے ہیں کیا خدا تعالیٰ بھی ایسا تو نہیں کہ وہ کسی کا خیال رکھے اور کسی کا نہ رکھے.اس شبہ کے ازالہ کے لئے فرمایا.لِرَبِّکَ.وہ نہ صرف سخی ہے اور خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بلکہ اے مخاطب اس کا تمہارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے.اس لئے تم یقین رکھو کہ تمہاری دعا ردّ نہیں ہو گی کیونکہ وہ صاحب ِ مقدرت بھی ہے صاحب سخاوت بھی ہے اور پھر اسے خاص طور پر تمہارا خیال بھی ہے.اس کے بعد فرمایا وَانْحَرْ.کوثر کے نتیجہ میں جہاں تُو نماز پڑھ اور دعائیں کر وہاں تو نحر بھی کر.یعنی بڑی بڑی قربانیاںکر.میں اوپر بتا چکا ہوں کہ کوثر کے تین معنے کئے جاتے ہیں جن میں سے ایک معنے یہ ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے.ان معنوں کے ساتھ فَصَلِّ لِرَبِّکَ کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا.یہ کہنا کہ تجھے جنت میں نہر ملے گی اس لئے تُو نماز پڑھ اور بڑی بڑی قربانیاں دے یہ ایک ایسا مفہوم ہے جو مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے.خدا تعالیٰ نے آپ سے کوثر
Page 185
سے بھی بڑی بڑی چیزوں کا وعدہ کیا مگر وہاں فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ کا حکم نہیں دیا.مثلاً لقاء الٰہی ہے.اس کا آپؐسے وعدہ کیا گیا لیکن وہاں نماز اور قربانی کا ذکر نہیں حالانکہ کجا نہر اور کجا محبوب کی ملاقات.اگر ایک چھوٹے انعام پر نمازوں اور قربانیوں کا حکم دیا گیا تھا تو چاہیے تھا کہ بڑے انعام پر اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ نمازوں اور قربانیوں کا حکم دیا جاتا.مگر ایسا نہیں کیا گیا.پس معلوم ہوا کہ نہر والے معنوں کے ساتھ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ کا کوئی جوڑ نہیں.لیکن اگر یہ معنے کئے جائیں کہ تجھے خیر کثیر ملے گی تو پھر اس آیت کا جوڑ باقی سورۃ سے نظر آجاتا ہے.کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے انعامات سے حصہ دیتا ہے تو اس کے بہت سے حاسدپیدا ہو جاتے ہیں.ملک میں ہزاروں ہزار علماء ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں.ہم فلاں فلاں کالج کے پرنسپل ہیں.فلاں فلاں کالج کے پروفیسر ہیں.فلاں فلاں جامع مسجد کے امام ہیں.لیکن ایک گمنام شخص جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی وہ ان کے سامنے یہ دعویٰ پیش کر دیتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے تم سب میری بیعت کرو.یہ سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے کہ ہم اس کی بیعت کیوں کریں.اِسے ہمارے مقابلہ میں کون سی پوزیشن حاصل ہے.گویا نبوت کے دعویٰ کے ساتھ ہی دنیا کے دوسرے لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے.اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے ہمارے رسول جو انعامات تم کو ملے ہیں یا آئندہ ملیں گے ایسے انعامات پر لوگ حسد کیا کرتے ہیں اور مخالفتیں کرتے ہیں.ان مخالفتوں کو دیکھتے ہوئے ابھی سے تیار ہو جاؤ اور دعائیں کرو.نماز پڑھو اور قربانیاں کرو تاکہ وہ بلائیں ٹل جائیں اوروہ آفات مٹ جائیں.چنانچہ کوثر کے پہلے معنوں کے رُو سے ہم دیکھتے ہیں کہ جوں جوں قرآن کریم نازل ہوتا گیا دشمن کا بُغض بھی بڑھتا گیا.مگر اس کے مقابل پر مسلمانوں میں بھی دعاؤں اور قربانیوں کا زور بڑھتا گیا اور انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لئے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کو اس طرح قربان کیا کہ اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتی.ایک دفعہ بعض لوگوں نے صحابہ ؓسے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر کون شخص تھا.جس طرح آج کل شیعہ سُنی کا سوال ہے اسی طرح اس زمانہ میں بھی جس کسی کے ساتھ تعلق ہوتا تھا لوگ اس کی تعریفیں کیا کرتے تھے.جب صحابہ ؓ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں سے سب سے بہادر وہ شخص سمجھا جاتا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا(تفسیر الخازن قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ.....) یہ نکتہ ایک جنگی آدمی ہی سمجھ سکتا ہے دوسرا آدمی نہیں.بات یہ ہے کہ جو شخص ملک اور قوم کی روح رواں ہو دشمن چاہتا ہے کہ اسے مار ڈالے تاکہ اس کی موت کے ساتھ تمام جھگڑا ختم ہوجائے اس لئے جس طرف بھی ایسا آدمی کھڑا ہو گا دشمن اس طرف پورے زور کے ساتھ حملہ کرے گا اور ایسی جگہ پر
Page 186
وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ بہادر ہو.پھر صحابہ ؓ نے کہا کہ آپ کے پاس اکثر حضرت ابو بکر ؓ کھڑے ہوا کرتے تھے اور ہمارے نزدیک وہی سب سے زیادہ بہادر تھے.میور جیسا اسلام کا شدید ترین دشمن لکھتا ہے کہ جب جنگ ِ احزاب ہوئی مسلمانوں کی تعداد اتنی کم تھی اور دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ وہ دشمن سے لڑائی کس طرح کرتے تھے.دشمن کی بہت بڑی تعداد تھی اور پھر وہ متواتر حملے کرتا تھا.کئی دن باریاں مقرر کر کے دشمن حملہ کرتا رہتا تھا تا چوبیس گھنٹے متواتر حملہ ہو سکے اور مسلمان تھک جائیں اس وقت مسلمان صرف بارہ سو کی تعداد میں تھے جن میں سے پانچ سو عورتوں کی حفاظت پر مقرر تھے.لڑنے والے لشکر کے صرف سات سو آدمی تھے لیکن دشمن کی تعداد پندرہ ہزار تھی.دشمن اگر اپنے لشکر کو پانچ حصوں میں بھی تقسیم کرتا تو ایک ایک وقت میں مسلمانوں کے سامنے کفار کا تین تین ہزار کا لشکر آتا تھا اور ہر حصہ کی قریباً پانچ پانچ گھنٹے باری آتی تھی.اس طرح وہ متواتر ۲۴گھنٹے لڑائی کر سکتا تھا.لیکن مسلمانوں کا لشکر اتنا تھوڑا تھا کہ وہ لشکر کو آدھا آدھا بھی نہیں کر سکتے تھے اور پھر ایک میل کا لمبا فرنٹ تھا جس پر وہ پھیلے ہوئے تھے.پس جب دشمن باری باری پانچ گھنٹے کے لئے حملہ کرتا تو مسلمانوں کو بغیر آرام چوبیس گھنٹے لڑنا پڑتا اور پھر بھی وہ دشمن کے مقابلہ پر صرف اس کی تعداد سے چوتھا حصہ لشکر لا سکتے تھے اور نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگوں کو سونے کا موقعہ نہ ملتا.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اس جنگ میں کئی دن سونے کا موقعہ نہ ملا.تاریخ میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے ہوئے کئی دن گذر گئے تو آپ نے اپنی ایک بیوی سے جو آپ کے پاس تھیں کہا کہ مجھے اتنے دن بغیر سوئے گذر گئے ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے اب کچھ سو لینا چاہیے تاکہ میری صحت قائم رہ سکے.لیکن دشمن چاروں طرف سے حملہ کر رہا ہے ہوشیاری سے کام لینا بھی ضروری ہے.اگر کوئی ایسا آدمی مل جائے جو خیمے کا پہرہ دے تو میں تھوڑی دیر کے لئے سو جاؤں اتنے میں باہر سے ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز آئی.آپ نے پوچھا کون ہے؟ ایک انصاری صحابی ؓ بولے یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ بہت دنوں سے سو نہیں سکے.لڑائی میں اب کچھ وقفہ تھا میں نے خیال کیا کہ میں چل کر خیمہ کا پہرہ دوں تا آپ تھوڑا سا سو لیں.یہ قربانی اور ایثار کی کتنی شاندار مثال ہے کہ آپ متواتر کئی دن جاگتے رہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں سوئے اور پھر جب آپ تھک گئے تو ایک صحابی جو خود آپ کی طرح جاگتا رہا تھا فوراً آپہنچا کہ میں پہر ہ دیتا ہوں آپ سو جائیں(بخاری کتاب الـجھاد بـاب الـحراسۃ فی الـغـزو فی سـبـیـل اللہ).یہی بات خدا تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ.تو دعائیں کر اور بڑی بڑی قربانیاں پیش کر.تمہارا مقابلہ بڑا سخت ہو گا.اگر تُو دعائیں کرتا گیا اور قربانیاں پیش کرتا
Page 187
رہا تو لازماً تیری خیر کثیر دشمن پر غالب آجائے گی.چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان دعاؤں اور قربانیوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ کوثر قائم ہو گیا اور دشمن کی مخالفت ختم ہو گئی.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کی اخبار اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہت دعائیں کیں اور مسیح موعود کو حوصلہ بھی دلایا کہ فرمایا جب مسیح و مہدی ظاہر ہوں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کے پاس گھٹنوں کے بل چل کر بھی جانا پڑے توجائیں(ابن ماجۃ کتاب الفتن باب خروج المھدی و مسند احمد بن حنبل مسند ابی ھریرۃ) اور یہ بھی فرمایا کہ میرا سلام ان کو پہنچائیں اور سلام کے معنے سلامتی کی دعا کے ہوتے ہیں.پس سلام پہنچانے سے یہ مراد ہے کہ ان کو کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اور آپ کے کام کی کامیابی کے لئے دعائیں کرتے گئے ہیں اس لئے مخالفتوں سے خوف نہ کرنا اور تسلی سے اپنا کام کئے جانا.آخری معنوں کے رُو سے اس آیت کے یہ معنے بنتے ہیں کہ اے ہمارے رسول خدا تعالیٰ تجھے ایک روحانی بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو بہت بڑی شان کا ہوگا.پس تُو جس طرح جسمانی بیٹے کی پیدائش پر لوگ شکر خدا کرتے ہیں اور بکروں کی قربانی کرتے ہیں اس شاندار بیٹے کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر شکر ادا کر اور بڑی بڑی قربانیاں پیش کر کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے تیرا نام قائم رکھے گا.اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُؒ۰۰۴ (اور)یقین رکھ کہ تیرا مخالف ہی نرینہ اولاد سے محروم (ثابت )ہوگا.حلّ لُغات.احادیث میں آتا ہے کہ بعض کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ تو نعوذباللہ ابتر ہے.اس کا سلسلہ بہت جلد ختم ہو جائے گا.اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ.لیکن چونکہ آپ کی بیٹیاں تھیں بیٹے نہیں تھے.اس لئے مفسرین کہتے ہیں کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کا کوئی بیٹا نہ ہو.لیکن اس کے عام معنے یہی ہیں کہ خواہ بالکل بے اولاد ہو یا نرینہ اولاد سے محروم ہو اسے ابتر کہتے ہیں تاج العروس جو عربی لغت کی دو بڑی کتابوں میں سے ایک ہے.اس میں لکھا ہے اَلْاَ بْتَرُ الْمُنْبَتِرُ الَّذِیْ لَا وَلَدَ لَہُ.ابتر اسے کہتے ہیں جو لا ولد ہونے کی صورت میں وفات پا جائے وَقَدْ یُقَالُ لَمْ یَکُنْ یَوْمًا وُلِدَ لَہٗ.اور اس شخص کو بھی ابتر کہا جاتا ہے جس کی کبھی بھی کوئی اولاد نہ ہوئی ہو.وَ فِیْہِ نَظَرٌ لیکن یہ درست نہیں.لِاَنَّہٗ وُلِدَ لَہٗ قَبْلَ الْبَعْثِ
Page 188
وَالْوَحْیِ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ابتر کہتے تھے حالانکہ بعثت اور وحی سے قبل دونوں وقتوں میں آپ کے اولاد پیدا ہوئی تھی.إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ أَرَادَ لَمْ يَعِشْ لَهٗ وَلَدٌ ذَكَرٌ.ہاں آپ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی تھی.گویا اگر کسی کی پہلے نرینہ اولاد موجود ہو لیکن بعد میں مر جائے تب بھی وہ ابتر کہلائے گا اور اگر پید اہی نہ ہو تب بھی وہ ابتر کہلائے گا.تفسیر.نبی کریمؐ کے دشمن کے ابتر رہنے کا مطلب ابتر کے معنے اوپر بتائے جاچکے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو یا جس کے ہاں کوئی لڑکا نہ ہو.چونکہ روایت میں آتا ہے کہ دشمن کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت ہے اور دشمن کا اعتراض یہ نہ تھا کہ آپ کے اولاد نہیں بلکہ یہ تھا کہ آپ کے ہاں لڑکا نہیں اس لئے اس آیت میں لڑکے کے معنے ہی کئے جائیں گے اور اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ کے یہ معنے ہوں گے کہ دشمن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لڑکا نہیں اور اس کے ہاں ہے.یہ دشمن جھوٹا ثابت ہو گا اور دنیا دیکھ لے گی کہ دشمن تو بغیر بیٹے کے رہے گااور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لڑکا ہو گا کیونکہ ’’تیرا دشمن ہی بغیر لڑکے کے ہو گا‘‘کے الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ دشمن کے ہاں لڑکا نہ ہو گا اورآپ کے ہاں ہو گا مگر جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے وہ سب صاحب ِ اولاد تھے بلکہ ان کی اولاد کی بھی آئندہ نسلیں چلیں اور ان میں سے کوئی بھی ابتر نہ رہا.ابو جہل کو ہی لو.وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا شدید دشمن تھا.مگر اس کا لڑکا عکرمہ ؓ موجود تھا جو جوان ہوا اور اس کی اولاد اب تک موجود ہے.مگر وہ ابو جہل کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتی.درمیان میں کسی اور دادا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتی ہے.اس کی اولاد عرب میں بھی پائی جاتی ہے ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہے اور پنجاب کے ضلع سرگودھا میں بھی پائی جاتی ہے.پھر آپ کے بڑے دشمن عتبہ اور ولید تھے.عتبہ کی اولاد کا مجھے علم نہیں لیکن ولید کے بیٹے حضرت خالد ؓ تھے.جن پر مسلمان آج تک فخر کرتے ہیں.پھر ان کی بھی آگے اولاد چلی.وہ عبد الرحمان خالد ؓ کا ہی بیٹا تھا جس کو انگریزی کتب میں سگیشس قاضی لکھا جاتا ہے یعنی عقلمند جج.حضرت عبد الرحمان بڑے ذہین اور سمجھدا ر تھے، بڑے دبدبہ والے تھے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں.پھر آپ کا بڑا دشمن عاصی تھا.حضرت عمروؓ بن عاص عاصی کے ہی بیٹے تھے جو اسلام کے ایک بڑے جرنیل گذرے ہیں.انہوں نے مصر فتح کیا.شام کی لڑائیاں لڑیں اور اپنے پیچھے اولاد چھوڑی آپ کے بیٹے عبد اللہ ؓ
Page 189
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابی تھے اور وہ اپنے باپ سے بھی پہلے چودہ سال کی عمر میں ایمان لے آئے تھے.باپ کفار کی طرف سے لڑائی میں شامل ہوتا تھا تو بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑائی میں شامل ہوتا تھا.پھر حضرت عبد اللہ ؓ کی بھی آگے اولاد چلی.پھر اسلام کے دشمن ابو سفیان کی بھی اولاد تھی.آپ کا بیٹا معاویہ ؓ تھا جس سے بنو امیہ ہوئے.جنہوں نے اسپین میں حکومت کی اور اب تک بھی ابو سفیان کی نسل پائی جاتی ہے.غرض آپ کے شدید سے شدید دشمن کی بھی اولاد چلی.بلکہ جن لوگوں کے متعلق روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو ابتر کہا وہ بھی صاحب ِ اولاد ہوئے اور ان کی نسل چلی مگر ان کے مقابلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی بیٹے ہوئے مگر فوت ہو گئے.آخری عمر میں ماریہ قبطیہ ؓ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے.مگر وہ بھی دو سال زندہ رہ کر فوت ہو گئے.اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ہم نے تجھے کوثر عطا فرمایا ہے جس کے نتیجہ میں تیرا دشمن ہی ابتر ہو گا اور اس کی نرینہ اولاد نہیں چلے گی مگر واقعات اس کے خلاف ہیں.آپ کے ہر دشمن کے ہاں قریباً لڑکے تھے اور ان کی نسلیں قائم رہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہا اور اس طرح آپ کی جسمانی نسل ختم ہو گئی.پس اس آیت پر یہ ایک بڑا بھاری اعتراض پیدا ہوتا ہے اور ایک مسلمان حیران ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا دے.اس اعتراض کے جواب میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ دراصل اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ کے مقابلہ میں ہے.یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے.پس تو دعائیں مانگ اور قربانیاں پیش کر.اس کے نتیجہ میں تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.میں بتا چکا ہوں کہ لُغت میں کوثر کے معنے اَلرَّجُلُ الْمِعْطَاء کے بھی آتے ہیں جس کے معنے ہیں بڑا سخی آدمی یا صاحب الخیر الکثیر.وہ آدمی جس کے اندر بڑی خیر اور برکت پائی جائے.پس آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ ہم تجھے ایک بہت بڑی خیرو برکت رکھنے والے اور سخی انسان دینے کی خبر دیتے ہیں.اس انسان کے ملنے کے شکریہ میں تُو دعائیں مانگ اور قربانیاں پیش کر.اس کے نتیجہ میں تیرا دشمن تو نرینہ اولاد سے محروم رہے گا اور تو نرینہ اولاد والا ہو جائے گا.میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یہ علامتیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں کہ رجل معطاء ہو گا اور صاحب الخیر الکثیر ہو گا یہ مسیح اور مہدی کی علامات ہیں اور اسی کے لئے فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ کا حکم ہے پس جس طرح اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ میں جسمانی اولاد مراد نہیں بلکہ روحانی اولاد مراد ہے اسی طرح اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ میں بھی جسمانی اولاد مراد نہیں بلکہ روحانی اولاد مراد ہے اور اللہ تعالیٰ اس امر کی
Page 190
طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تیرا دشمن اپنے عقائد کو چلانےوالی نسل سے ہمیشہ کے لئے محروم رہے گا لیکن تُو صاحب اولاد ہو گا چنانچہ دیکھ لو عکرمہؓ جسمانی طور پر ابو جہل کا بیٹا تھا لیکن وہ مسلمان ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن گیا.گویا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میری اولاد موجود ہے.آخر یہ سوچنے والی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے سے دشمن کی مراد کیا تھی.اس کی مراد یہی تھی کہ ہمارے عقائد کو ہمارے بعد قائم رکھنے والی اولاد موجود ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو قائم رکھنے والی اولاد موجود نہیں.اس لئے ان کا قائم کردہ سلسلہ جلد ہی تباہ ہو جائے گا لیکن جب ابو جہل کا بیٹا عکرمہ ؓ مسلمان ہو گیا اور اسلام کے لئے اس نے قربانیاں کیں تو جو دعویٰ ابو جہل نے کیا تھا وہ جھوٹا ہو گیا کیونکہ اس کا اپنا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کو پھیلانے لگ گیا.ابو جہل سمجھتا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو میرے خیالات اور عقائد کو قائم رکھنے کے لئے اولاد موجود ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قائم نہیں رہے گی اس لئے کہ آپ کی اولاد موجود نہیں.مگر جب اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہو گیا تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہو گیا.پھر ولید اسلام کا بڑا دشمن تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ میری اولاد میرے عقائد کو قائم رکھے گی لیکن اس کا بیٹا خالد ؓ مسلمان ہو گیا اور اس نے اسلام کے لئے ایسی شاندار قربانیاں کیں کہ آج بھی ہم بہادری کی مثال دیتے وقت کہتے ہیں کہ تم خالد ؓ بنو.یہ خالدؓ وہی ہے جو ولید کا بیٹا تھا.وہ ولید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین مخالفت کیا کرتا تھا جو آپ پر گند پھینکا کرتا تھا اور جو نماز پڑھتے وقت آپ پر جانوروں کی اوجھریاں ڈال دیتا تھا.اس کا اپنا بیٹا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی اور جاں نثار ثابت ہوا اور اس نے ساری عمر اسلام کی خدمت میں بسر کر دی.جب خالدؓ آپؐ کے متبع ہوئے اور آپ پر قربان اور فدا ہوئے تو گویا خالد ؓ آپ کا بیٹا بن گیا اور ولید اولاد سے محروم ہو گیا.پھر عاص ہے یہ بڈھا رات دن لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہتا تھا اور اسلام کا شدید ترین دشمن تھا مگر اس کے بیٹے حضرت عمروؓ آپؐپر ایمان لائے اور وہ بڑے پایہ کے صحابیؓ ثابت ہوئے.مصر آپ نے ہی فتح کیا تھا اور شام کی لڑائیاںبھی آپ نے ہی لڑیں.گویا عاص بے اولاد رہا کیونکہ اس کی اپنی اولاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بن گئی.پھر ابو سفیان تو خود ہی مسلمان ہو گیا تھا اس لئے اس کی دشمنی کا کوئی سوال ہی نہ رہا.اس کے بیٹے حضرت معاویہ ؓ تھے وہ بھی اسلام کے بڑے خدمت گذار ثابت ہوئے.غرض گو جسمانی اولاد کے لحاظ سے اس آیت کے کوئی معنے نہیں بنتے لیکن اگر روحانی معنے مراد لئے جائیں تو یہ آیت ایک زندہ حقیقت ثابت ہوتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابو جہل لا ولد تھا.کیونکہ اس کے خیالات اور عقائد کو چلانے والی اولاد موجود نہیں تھی.ولید لا ولد تھا کیونکہ اس کی اولاد بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی متبع ہو گئی عاص لا ولد تھا کیونکہ
Page 191
گو اس کی اولاد چلی مگر اس کے عقائد اور خیالات کو اس نے نہیں پھیلایا.بلکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پھیلانے میں لگ گئی.پس یہاں اولاد سے جسمانی اولاد مراد نہیں بلکہ روحانی اولاد ہے.اگر جسمانی اولاد مراد لی جائے تو آیت کی دونوں دلالتیں غلط ہو جاتی ہیں.کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کے دشمن کی نرینہ اولاد نہیں ہو گی حالانکہ اس کی اولاد تھی.اور پھر کہا گیا ہے کہ آپ کی نرینہ اولاد ہو گی حالانکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی.لیکن اگر روحانی معنے مراد لئے جائیں تو دونوں باتیں صحیح ہوجاتی ہیں.یہ بات بھی صحیح ہو جاتی ہے کہ ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں تھی.ولید کی کوئی اولاد نہیں تھی.عاص کی کوئی اولاد نہیں تھی اور یہ بات بھی صحیح ہو جاتی کہ آپ کی روحانی اولاد کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا.عتبہ کی نسل کے متعلق مجھے اِ س وقت یاد نہیں کہ اس کی ظاہری نسل چلی تھی یا نہیں.لیکن اگر اس کی نسل ہو گی بھی تو وہ مسلمانوں میں ہی چھپی ہو گی بہر حال اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ مضمون بیان فرما تا ہے کہ ہم تجھے ایک خیر کثیر رکھنے والا روحانی بیٹا عطا فرمائیں گے جس سے دنیا پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ تُو نہیں بلکہ تیرا دشمن ہی نرینہ اولاد سے محروم ہے.یہاں ایک اور بات بھی مدّ ِنظر رکھنے والی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیتا ہے.جب وہ مومنوں کی مائیں ہوئیں تو لازماً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہوئے اور تما م مومن آپ کی اولاد میں شامل ہو گئے.اب اولاد میں لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں.مگر اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ اور اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ میں یہ خبر دی گئی ہے کہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایک خیر کثیر رکھنے والا روحانی بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس کا دشمن نرینہ اولاد سے محروم ہو گا.اب لازماً کوئی ایسا رتبہ اور عہدہ بھی ہونا چاہیے جو اس اولاد کو نرینہ اولاد ثابت کر دے اور جس کے وجود سے یہ ثابت ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرینہ اولاد سے محروم نہ تھے.اس نقطۂ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا عہدہ تو لڑکیوں کے لئے بھی ہے اور لڑکوں کے لئے بھی.شہادت اور صدیقیت کے مقامات بھی مرد کی طرح عورتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں لیکن نبوت ایک ایسا عہدہ ہے جو کبھی کسی عورت کو نہیں ملا.اور یہ مرد کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے.یہاں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے روحانی بیٹے کی خوشخبری دی گئی ہے اس لئے آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ تیرے دشمن کی اولاد کٹ جائے گی لیکن تیری نسل میں سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا انسان پیدا کرے گا جو نبوت کے مقام پر فائز ہو گا.یہی مضمون ایک اور جگہ بھی بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ
Page 192
رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ١ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا (الاحزاب:۴۱) یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہے.یہ آیت سورۂ احزاب کی ہے جو ہجرت کے چوتھے سال میں نازل ہوئی تھی.اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں.لیکن سورۃ کوثر میں جو ابتدائی ایام نبوت میں نازل ہوئی تھی.اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ.تیرا دشمن ہی نرینہ اولاد سے محروم رہے گا تُو نرینہ اولاد سے محروم نہیں ہو گا.اب بظاہر ان دونوں آیات میں بڑا تضاد نظر آتا تھا اور انسان حیران ہوتا تھا کہ یہ بات کیا ہے کہ وہاں تو کہا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہو گی مگر یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہو گی.گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ وہ اعتراض جو کفار مکہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذباللہ ابتر ہیں اس اعتراض کو خود قرآن کریم نے تسلیم کر لیا اور کہہ دیا کہ آپؐمردوں میں سے کسی کے باپ نہ ہیں نہ آئندہ ہوں گے.رَجُلٌ کے معنے مرد اور کامل انسان کے ہوتے ہیں اور اکثر اہل لغت اسے جوان مرد کے لئے استعمال کرتے ہیں.اور گو بعض ذَکر کے معنے بھی لیتے ہیں لیکن عربی کا عام استعمال مرد کے لئے ہی ہے.تاج العروس میں لکھا ہے اِنَّـمَا ھُوَ فَوْقَ الْغُلَامِ وَ ذَالِکَ اِذَااحْتَلَمَ وَ شَبَّ یعنی لڑکا جب بالغ ہو جائے اور جوانی کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے رجل کہتے ہیں.گو اس کے بر خلاف محض ذکر کے معنے بھی لکھے ہیں مگر محاورہ میں اس کی سند نہیں صرف بعض علماء کا قول ہے پس مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ سے مراد یہی ہے کہ آپ کی ذکور اولاد میں سے کوئی بلوغ کو نہیں پہنچا.اس وقت بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں پہنچے گا.پس پہلی نرینہ اولاد اور بعد کی اولاد اس آیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی بلوغ کو نہیں پہنچا.اس آیت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یہ تھی (۱)سب سے پہلے قاسم ہوئے جن سے آپ کی کنیت مشہور ہے اور آپ ابو القاسم کہلاتے تھے.صحیح تاریخوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ چھوٹے بچے تھے کہ فوت ہو گئے گو بعض روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ سواری پر چڑھنے کے قابل ہو گئے تھے تب بھی بلوغ کسی تاریخ اور حدیث سے ثابت نہیں اور یہ روایت بھی کمزور ہے.(۲)دوسرے بیٹے عبد اللہ تھے.ان کے لقب الطیب اور الطاہر بھی ہیں.بعض کے نزدیک یہ دعویٰ نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور بعض مؤرخین کے نزدیک یہ دعویٰ نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے زیادہ صحیح یہی ہے کہ دعویٰ نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے کیونکہ مضبوط اور قوی روایتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے.الطیب اور الطاہر ناموں کے متعلق یہ معلوم نہیں
Page 193
ہوتا کہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ نام رکھے تھے یا آپ نے تو ایک ہی نام رکھا تھا مگر ابو طالب یا حضرت خدیجہ ؓ نے پیار سے دوسرے نام بھی رکھ دیئے تھے.معتبر روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی بچے کے دو نام تھے.گو بعض کمزور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ دونوں نام الگ الگ بچوں کے تھے.قاسم اور طیب دونوں ہی بچپن میں فوت ہو گئے تھے.قاسم نے جب وفات پائی ان کی عمر سات آٹھ برس کی تھی اور عبد اللہ دو تین سال کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے.(۳)تیسرا بچہ آپ کے ہاں اس آیت کے بعد ماریہ قبطیہ ؓ سے ہوا، جسے مقوقس گورنر مصر نے بطور ہدیہ بھجوایا تھا.اس بچہ کا نام ابراہیم تھا.یہ ۸ھ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات ۲۹ شوال ۱۰ ھ کو ہوئی(انگریزی مہینوں کے حساب سے یہ تاریخ ۲۷جنوری ۶۳۷ء بنتی ہے )گویا ۲ سال کے قریب آپ کے صاحبزادہ حضرت ابراہیم زندہ رہے( السیرۃ النبویۃ لابن ھشام تزویج رسول اللہ خدیجۃ و السیرۃ الحلبیۃ باب ذکر اولادہ) ان تینوں لڑکوں کی عمروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی رَجُل نہیں ہوا اور یہی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہ کبھی ہوئے ہیں، نہ اب ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے.گویا ماضی میں بھی آپ کی کوئی اولاد بلوغت کو نہیں پہنچی تھی اور جب یہ سورۃ نازل ہوئی اس وقت بھی آپ کے ہاں بالغ نرینہ اولاد موجود نہ تھی اور آئندہ بھی کوئی لڑکا بلوغت کو نہیں پہنچے گا.گویا تینوں زمانوں کے لحاظ سے آپ کی ابوّت کی نفی کی گئی ہے اور اس طرح لے پالک کے طریق کا جو عرب میں رائج تھا اور جس کے ذریعہ سے پالے ہوئے بچہ کو صلب سے پیدا ہونے والے بچہ کا رتبہ دیا جاتا تھا ردّ کیا گیا ہے مگر اس اعلان نے لوگوں کے دلوں میں ایک نیا شک پیدا کر دیا.اگر تو آیت یہ ہوتی کہ لَیْسَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ تب تو کوئی شبہ نہ ہوتا کیونکہ یہ ایک امر واقعہ تھا کہ آپ کے ہاں اولاد ِ نرینہ بالغ نہ تھی.اس سے مستقبل پر کوئی روشنی نہ پڑتی تھی.مگر مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ کہہ کر مستقبل کے متعلق بھی پیشگوئی کر دی گئی اور اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ کی پیشگوئی کی گویا واضح طور پر تردید ہو گئی.یہ آیات ۴ ہجری کے شروع میں نازل ہوئی ہیں.اس کے بعد ۸ ہجری میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو ۱۰ھ میں فوت ہو گئے.گویا دشمن کو د۲و خوشیاں نصیب ہوئیں.پہلی خوشی تو اس نے ابتر کہہ کر حاصل کی.اس کے بعدجبکہ سولہ سال تک آپ کے ہاں اولاد نہ ہوئی اور بظاہر مایوسی ہو گئی یہ آیت نازل ہوئی اور دشمن نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب چونکہ اولاد سے مایوسی ہو گئی ہے پہلی پیشگوئی کو بدل کر ایک نئی پیشگوئی کر دی گئی ہے.تاکہ اس الزام کو کہ آپ کے ہاں اولاد نرینہ نہیں اپنے فائدہ کے لئے استعمال کیا جائے اور کہا جائے کہ گویا نرینہ اولاد کا نہ ہونا ہماری پیشگوئی کے نتیجہ میں ہے اور ہماری سچائی کی علامت ہے لیکن اولاد کا انقطاع جو سولہ سال سے چلا آتا تھا اس پیشگوئی
Page 194
کے نزول کے بعد یک دم ختم ہو گیا اور اُنیس سال بعد آپ کے ہاں ایک نرینہ اولاد پیدا ہو گئی یعنی حضرت ابراہیم پیدا ہو گئے.اب پھر دشمن کے لئے ایک اور خوشی کا موقعہ بہم پہنچا کہ دیکھو جو دوسری پیشگوئی کی گئی تھی وہ بھی غلط ہو گئی اور لڑکا پیدا ہو گیا.کون مسلمان اس وقت کہہ سکتا تھا کہ کیا معلوم یہ لڑکا زندہ بھی رہے گا یا نہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ فقرہ زبان پر کب آنے دے سکتی تھی.مگر آخر دسویں سال ہجری میں وہ لڑکا بھی فوت ہو گیا اور یہ اعتراض بھی دور ہو گیا لیکن پہلا اعتراض کہ آپ تو کہتے تھے کہ اولاد نرینہ ہو گی باقی رہ گیا.اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ.لٰكِنْ کا لفظ استدراک کے لئے آتا ہے یعنی پہلے جملہ سے جو وہم یا شبہ پیدا ہو اس کا ازالہ اس کے بعد کے جملہ سے کیاجاتا ہے خواہ وہ شبہ خود عبارت سے پیدا ہوتا ہو یا اس کے متعلقات سے پیدا ہوتا ہو.یہ لٰكِنْ کا لفظ کبھی خالی آتا ہے اور کبھی اس سے پہلے واولایا جاتا ہے جیسے وَ لٰكِنْ.پھر کبھی یہ مشدد ہوتا ہے اور کبھی غیر مشدد ہوتا ہے.لیکن جب بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ازالہ شبہ کے لئے ہی ہوتا ہے.اب سوال یہ ہے کہ پہلے فقرہ یعنی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ سے کون سا شبہ پیدا ہوتا تھا جس کا ازالہ کرنے کی ضرورت پیش آتی.سوجیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اس جگہ یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ سورہ ٔ کوثر میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کا دشمن ابتر رہے گا اور آپ کے ہاں نرینہ اولاد ہو گی.مگر اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی بالغ نرینہ اولاد نہ پہلے تھی نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہو گی.گویا پہلے تو کہا کہ آپ کے ہاں اولاد ہو گی مگر بعد میں اس کے اُلٹ کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہوگی.اس شبہ کا ازالہ خدا تعالیٰ دو لفظوں سے کرتا ہے یعنی رسول اللہ اور خاتم النبیین سے.یہاں واؤ عطف کا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس غرض کے لئے پہلا لفظ یعنی رسول آیا ہے اسی غرض کے لئے دوسرا لفظ یعنی خاتم النبیین لایا گیا ہے.اُردو میں بھی ہم کہتے ہیں زید گیا اور بکر.اور ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فعل زید سے ہوا وہی بکر سے ہوا.یا کہا جاتا ہے میں نے گوشت کھایا اور روٹی.اس کامطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ میں نے گوشت بھی کھایا اور روٹی بھی.پس عطف کے بعد کا جملہ عطف سے پہلے کے جملہ سے معنوں میں شریک ہوتا ہے.اس لحاظ سے وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ میںرسول کا لفظ جس شبہ کے ازالہ کے لئے آیا ہے اسی شبہ کے ازالہ کے لیے خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے.اور وہ شبہ یہ تھا کہ اگر یہ درست ہے کہ آپ کے ہاں بالغ نرینہ اولاد نہ پہلے تھی نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوگی تو پھر سورۃ کوثر والی پیشگوئی جھوٹی نکلی اور اگر وہ پیشگوئی جھوٹی ثابت ہوئی ہے تو پھر آپ اس کے رسول نہیں ہوسکتے.اس شبہ کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک تویہ دلیل دی کہ آپ رسول اللہ ہیں یعنی آپ کی رسالت دوسرے بیّن دلائل سے ثابت ہے کسی ایک دلیل سے آپ خدا تعالیٰ کے رسول ثابت نہیں
Page 195
ہوئے آپ کی صداقت کے بیسیوں دلائل ہیں.قرآن کریم میں بھی آپ کی صداقت کے دلائل پائے جاتے ہیں تورات سے بھی آپ کی صداقت کے دلائل ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آپ کی صداقت کی دلیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیاں بھی آپ کی صداقت واضح کر رہی ہیں.یسعیاہ ؑ نے بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں.یرمیاہ ؑ نے بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں.حزقیل ؑ نے بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں اور ان کے علاوہ کئی دوسرے انبیاء نے بھی آپ کے متعلق پیشگوئیاں کی ہیں اور وہ سب کی سب آپ پر پوری ہورہی ہیں.کسی ایک پیشگوئی میں شبہ پڑ جانے سے دوسری پیشگوئیاں کس طرح باطل ہو گئیں.اگر کسی شخص کی آنکھ کے عصبہ پر فالج پڑے اور دوپہر کا وقت ہو تو اسے اردگرد اندھیرا نظر آئے گا.مگر اس دلیل سے یہ تو ثابت نہیں ہو گا کہ واقعہ میں رات پڑگئی ہے کیونکہ دن کی دوسری علامات موجود ہوتی ہیں.مثلاً تمازتِ آفتاب ہے، گرمی ہے، لوگوں کا اِدھر اُدھر کاموں میں مشغول ہوناہے.اگر یہ علامات موجود ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ اس شخص کو تاریکی دکھائی دے رہی ہے یہ ثابت نہیں ہوجائے گا کہ واقعہ میں رات پڑگئی ہے.جس طرح وہاں ایک دلیل کے پائے جانے سے رات ثابت نہیں ہوتی اسی طرح یہاں کسی ایک پیشگوئی میں شبہ پیدا ہونے سے آپ کی رسالت پر اثر نہیں پڑ سکتا.یہی دلیل قرآن کریم نے ایک اور مقام پر بھی دی ہے جب جنگ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ شہید ہوگئے ہیں اور کئی صحابہ ؓ اپنی ہمت ہار بیٹھے تو خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ١ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ١ؕ اَفَاۡىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ ( اٰل عمران :۱۴۵) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے بہت سے اور رسول بھی گذر چکے ہیں اگر آپ قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپؐنعوذباللہ راستباز نہیں اور تم مرتد ہو جاؤ گے.یہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو اگر آپ کی نبوت میں کوئی شبہ پڑ سکتا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ فوت کیوں ہوئے بلکہ اس وجہ سے کہ آپ کے متعلق یہ پیشگوئی موجود تھی کہ وَاللّٰہُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ(المآئدۃ:۶۸) اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کے ہاتھ سے قتل نہیں ہونے دے گا اگر آپ مارے جاتے تو یہ پیشگوئی غلط ثابت ہو جاتی.اللہ تعالیٰ اسی پیشگوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی ایک پیشگوئی کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ثابت نہیں ہو سکتے.آپ کا جھوٹا ہونا تو تب ثابت ہو گا جب آپ میں نبوت کی شرائط نہ پائی جائیں اور قتل نہ ہونا نبوت کی شرط نہیں.جب قتل نہ ہونا نبوت کی شرط نہیں تو پھر ایک پیشگوئی کے غلط ہونے سے آپ جھوٹے ثابت کیسے ہوئے.آپ کی صداقت کے اور بھی تو بیسیوں دلائل اور براہین ہیں.جب وہ دلائل آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں
Page 196
تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ پیشگوئی جو ہمارے زعم میں جھوٹی ثابت ہوئی ہے اس کے کوئی اور معنے تھے جوہماری سمجھ میں نہیںآئے.اگر آپ جھوٹے ہوتے تو دوسری علامات آپ میں کیوں پوری ہوتیں اور دوسرے دلائل آپ کی صداقت پر کیوں موجود ہوتے.یہاں بھی وہی دلیل دی گئی ہے کہ آپ کی صداقت اور رسالت تو اور دلائل سے بھی ثابت ہے.موسٰی کی پیشگوئیاں موجود ہیں، عیسیٰ ؑ کی پیشگوئیاں موجود ہیں، داؤد ؑ کی پیشگوئیاں موجود ہیں، یسعیاہ ؑ کی پیشگوئیاں موجود ہیں، یرمیاہ ؑ کی پیشگوئیاں موجود ہیں، دانیال ؑ کی پیشگوئیاں موجود ہیں اور دوسرے کئی انبیاء کی پیشگوئیاں موجود ہیں.پھر آپ کو ایک بے مثال کلام دیا گیا.قوت ِ قدسیہ عطا کی گئی.آپ کو دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوا.آپ کو نصرتِ الٰہی حاصل ہوئی.ان سب دلیلوں کے ہوتے ہوئے اگر ایک دلیل کسی شخص کی سمجھ میں نہیں آئی تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ہمیں غلطی لگی ہے یہ بہرحال جھوٹا نہیں.پس وَلٰکِنْ رَّسُوْلَ اللّٰہِ کہہ کر اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اگر آ پ کی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی تو اس سے آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا یہ استدلال بالکل غلط ہے.باوجود اس کے کہ آیت اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ کے بظاہر خلاف یہ آیت مضمون رکھتی ہے پھر بھی اس کے سچا ہونے میں شک نہیں کیونکہ یہ رسول اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تفصیلی پیغام لایا ہے اگر ایک بات میں شک ہو تو تم اور ہزاروں پیغاموں کو کدھر لے جاؤ گے.حق تو یہ ہے کہ ایک بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ثابت ہو جائے اور دس بیس مشتبہ ہو جائیں تو تقویٰ چاہتا ہے کہ ہم تکذیب میں جلدی نہ کریں.کیونکہ جو سچ ہوئی اس کی ہم تاویل کچھ نہیں کر سکتے.لیکن جب بات یہ ہو کہ کلام کے بعد کلام پورا ہوا ہو تو اگر ایک بات نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس کی بنا پر ہم تکذیب ہرگز نہیں کر سکتے بلکہ اپنی عقل کا قصور قرار دیں گے اور اسے غلط نہیں کہیں گے، تشریح طلب کہیں گے.اب سوال یہ ہے کہ مان لیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ بہرحال سچے ہیں اور آپ کی راستبازی پر ہمارا ایمان ہے.لیکن ایک کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میرے شبہ کو دور کرنا بھی تو خدا تعالیٰ کا کام ہے.آخر جو مجھے شبہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا جواب ہے.اس کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ آپ خاتم النبیین ہیں.خَاتم کے معنے مُہر کے ہوتے ہیں اورمہر کی غرض تصدیق کرنا ہوتی ہے.چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے تو واقف کار صحابہ ؓ نے عرض کیا کہ بادشاہ بغیر مہر کے خط کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے.اس پر آپ نے ایک مہر بنوائی جس میں سب سے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا اس کے نیچے رسول کا لفظ تھا اور اس کے نیچے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا لفظ تھا.گویا اس کی شکل یہ تھی یہ مہر آپ نے اسی لئے بنوائی کہ آپ اسے
Page 197
خط پر ثبت کر کے تصدیق کر سکیں کہ یہ خط واقعہ میں میری طرف سے لکھا گیا ہے(بخاری کتاب اللباس باب نقش الخاتم) آج کل عدالتیں بھی یہ لکھا کرتی ہیں کہ فلاں اشتہار بمہر عدالت جاری ہوا.یعنی عدالت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اشتہار ہماری طرف سے ہے پس نبیوں کی مہر کے یہ معنے ہوئے کہ آپ نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جس پر آپ کی مہر ہو گی وہ نبی ہو گا اور جس پر آپ کی مہر نہیں ہو گی وہ نبی نہیں ہو گا.پھر مُہر ہر کسی چیز پر نہیں لگائی جاتی بلکہ صرف اس چیز پر لگائی جاتی ہے جو اپنی ہو.پس خاتم النبیین کے الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپؐکے بعد صرف وہ نبوت جاری ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور غلامی میں ہو.اگر آپ کے بعد کوئی ایسا آدمی کھڑا ہوجاتا ہے جو کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نعوذباللہ ختم ہو گئی ہے تو وہ جھوٹا ہے.کیونکہ آپ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا.بلکہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نبوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوں تب بھی وہ جھوٹا ہے کیونکہ کوئی شخص درجہ میں آپ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا.لیکن وہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے اس مقام پر اس لئے فائز کیا ہے تا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کروں اور مجھے جو کچھ ملا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اطاعت میں ملا ہے.اگر قرآن کریم اور احادیث نبوی اس کی تصدیق کریں تو اس کا دعویٰ نبوت سچا ہو گا کیونکہ ایسے شخص پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مُہر ہوگی اور جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو وہ اُمتی اور شاگرد ہونے کی وجہ سے آپ کا روحانی بیٹا ہو گا اور درحقیقت یہی وہ بیٹا تھا جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ کوثر میں بشارت دی گئی تھی.مگر لوگوں نے غلطی سے اسے ظاہری اولاد پر چسپاں کر لیا.اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب میں اس شبہ کا ازالہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ تمہاری اپنی غلطی تھی کہ تم نے اس آیت کو ظاہری اولاد پر چسپاں کر لیا.ہماری مراد تو روحانی اولاد سے تھی اور ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ مقام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ آپ کی غلامی اور متابعت میں انسان نبوت کا مقام بھی حاصل کر سکتا ہے جو مقام صرف مردوں کو ملتا ہے عورتوں کو نہیں.پس ایسے شخص کے پیدا ہونے سے ثابت ہو جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اولاد کے باپ ہیں اور آپ کا دشمن اس اولاد سے محروم ہے.گویا آپ کی روحانی اولاد کا سلسلہ ہمیشہ ایسے رنگ میں جاری رہے گا کہ آپ کی غلامی میں انسان بڑے سے بڑا روحانی مقام بھی حاصل کر سکے گااور یہ ثبوت ہو گا اس بات کا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے مگر آپ کا دشمن اس سے کلی طور پر محروم ہے.پھر پچھلے انبیاء کی نبوت بھی آپ کی تصدیق کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی.اور نبیوں کو جانے دو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی نبوت ہی ہم کیسے مان سکتے تھے اگر قرآن کریم نہ کہتا کہ وہ نبی ہیں.
Page 198
تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات درج ہیں ان سے تو آپ کی نبوت ثابت نہیں ہو سکتی.لیکن قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ وہ سچے نبی تھے اور اس تصدیق کی وجہ سے ہم موسٰی کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں.گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اس لئے نہیں مانا کہ تورات کہتی ہے کہ وہ نبی ہیں بلکہ ہم نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مُہر کی وجہ سے نبی مانا ہے.اسی طرح قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ نبی تھے تو ہم نے بھی انہیں نبی مان لیا.ورنہ انجیل پڑھ کر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مان سکتے تھے.انجیل میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ شراب پی رہے تھے.حضرت مریم صدیقہ بھی اسی محفل میں شریک تھیں کہ شراب ختم ہوگئی.حضرت مریم بہت گھبرائیں کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور شراب ختم ہو گئی ہے بہت بدنامی ہو گی.انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پانی کے مٹکوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ شراب کے بن گئے.(یوحنا باب ۲ آیت ۱تا۱۱) پھر لکھا ہے کہ آپ کے شاگرد ایک دفعہ کسی کے کھیت میں گھس گئے اور مالک کی اجازت کے بغیر انہوں نے پھل کھایا.لوگوں نے شکایت کی تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے.آپ نے کھیت والوں کو ڈانٹا اور کہا دولہا کی موجودگی میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا(متی باب ۱۲ آیت ۱ تا ۸) اسی طرح انجیل میں لکھا ہے کہ سؤروں کا ایک ریوڑ چر رہا تھا.آپ نے ان پر بھوت چڑھا دیئے اور وہ سب کے سب دریا میں کود کر ڈوب گئے.گویا دوسرے کا آپ نے شدید مالی نقصان کیا(لوقا باب ۸ آیت ۲۶ تا ۳۴) ان انجیلی واقعات کی موجودگی میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں نبی مان سکتے تھے.ہم تو ان کو اگر نبی مانتے ہیں تو اس لئے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ نبی تھے.جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نبی تھے جب قرآن کریم نے کہا کہ آپ نبی تھے تو ہم نے بھی مان لیا کہ آپ نبی تھے.اسی طرح اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص آتا ہے جو آپ کی تعلیم کو جھوٹا قرار دیتا ہے یا آپ پر عیب چینی کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہو گا.کیونکہ اس کی نبوت پر آپ کی مہر نہیں ہو گی.ہاں اگر وہ آپ کے نقشِ قدم پر چلنے والا ہو گا اور آپ کی پیشگوئیاں اس کے حق میں ہوں گی تو ایسے نبی کے آنے سے آپ کی ہتک نہ ہوگی.کیونکہ وہ آپ کے کمالات کو ظاہر کرنے والا ہو گا.اور وہ کوئی غیر وجود نہیں ہو گا بلکہ آپ کا ہی روحانی بیٹا ہو گا.میں اس موقعہ پر یہ ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ عام مسلمان خاتم النبیین کے یہ معنے کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں.اور وہ اس کی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِیَآءِ وَمَسْجِدِیْ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ (مسلم کتاب الـحج بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ بِـمَسْجِدَيْ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ) میں نبیوں میں
Page 199
سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے سو اس بارہ میں یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث کا دوسرا حصہ اس کے پہلے حصہ کے معنوں کی وضاحت کر دیتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِیَآءِ بلکہ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مَسْجِدِیْ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ.میری مسجد تمام مساجد میں آخری مسجد ہے.اب کیا کوئی مسلمان اس کے یہ معنے کر سکتا ہے کہ مسجد نبوی کے بعد اور کوئی مسجد نہیں بن سکتی.خود مسلمانوں نے دنیا میں ہزاروں ہزار مسجدیں بنوائی ہیں.جن کی تقدیس کا کوئی شخص انکار نہیں کرتا.اگر اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ کے یہی معنی ہوتے کہ مسجد نبوی کے بعد کوئی مسجد نہیں بن سکتی تو مسلمان ہرملک اور ہر علاقہ اور ہر شہر اور ہر قصبہ بلکہ ہر گاؤں میں کیوں مساجد بناتے.ان کا جگہ جگہ مسجدیں بنانا بتاتا ہے کہ وہ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ کے یہی معنے سمجھتے ہیں کہ آئندہ وہی مسجد مسجد کہلا سکتی ہے جو مسجد نبوی کی نقل میں بنوائی گئی ہو.اگر آپ کی مسجد کے بعد دوسری مساجد کا بننا اس صورت میں کہ وہ آپ کی مسجد کی نقل ہوں، اس حدیث کو ردّ نہیں کرتا تو ایک ایسے نبی کا آنا جو آپ سے الگ نہ ہو بلکہ آپ کا تابع اور اُمتی ہو، وہ آپ کے آخر الانبیاء ہونے کو کس طرح ردّ کر سکتا ہے.معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ زمانہ میں لوگوں کے دلوں میں جو وساوس پیدا ہونے والے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہوئے اَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِیَآءِ کہنے کے ساتھ ہی وَمَسْجِدِیْ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ بھی کہہ دیا.تالوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اٰخِر کے کیا معنے ہیں.جس طرح وہ مسجد جو آپ کی مسجد کی نقل میں بنائی گئی ہو آپ کی مسجد کی آخریت کو نہیں توڑتی اسی طرح وہ نبی جو آپ کے نقش قدم پر آئے، آپ کا تابع اور اُمتی ہو.وہ آپ کی آخریت کو نہیں توڑتا.گویا ایسا نبی جو آپ کے نقش قدم پر نہ آئے جو اپنے آپ کو مستقل نبی قرار دے اور جو آپ کے فیضان کا انکار کرے وہ تو آپ کی نبوت کی آخریت کو توڑنے والا ہے لیکن ایسا نبی جو آ پ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو، آپ کی شریعت کو جاری کرنے والا ہو اور اس کا وہی کلمہ ہو جو اسلام کا کلمہ ہے.وہی نمازیں ہوں جو اسلام میں پائی جاتی ہیں.وہی تعلیم ہو جو اسلام کی تعلیم ہے تو وہ آپ کی نبوت کی آخریت کو توڑنے والا نہیں ہو گا.جیسے ایک مسجد جس کا قبلہ وہی ہو جو آپ کی مسجد کا قبلہ تھا اس میں اسی طرح نمازیں پڑھی جائیں جس طرح آپ کی مسجد میں پڑھی جاتی تھیں اور ان نمازوں میں وہی الفاظ ادا کئے جائیں جو آپ نے ادا کئے وہ آپ کی مسجد کی آخریت کی ناقض نہیں اور نہ ایسی مسجد بنانے سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ کی مسجد آخری مسجد نہیں.وہ تو دراصل آپ کی مسجد کا ہی ایک حصہ ہوگی اور کسی چیز کا حصہ ہونا اصل کا ناقض نہیں ہوتا.اسی طرح وہ نبی جو آپ کا شاگرد ہو آپ کا روحانی فرزند ہو آپ کے فیوض سے اسے یہ مقام حاصل ہوا ہو، آپ کی شریعت کو جاری
Page 200
کرنے والا ہو، آپ کے لائے ہوئے دین کو قائم کرنے والا ہو، وہ بھی آپ کے آخری نبی ہونے کو نہیں توڑتا.بلکہ وہ آپ کے وجود میں ہی شامل ہو گا.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ہاتھ جسم کا ایک حصہ ہے.اس کے متعلق کوئی شخص یہ نہیں کہا کرتا کہ جسم الگ چیز ہے اور ہاتھ الگ.یا سائے کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی نیا آدمی ہے.پس مَسْجِدِیْ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ کے فقرہ نے اَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِیَآءِ کے فقرہ کو حل کر دیا.جس طرح آپ کی مسجد کی نقل میں کوئی مسجد بنانا آپ کی مسجد کی آخریت کو نہیں توڑتا.اسی طرح ایسا نبی جو آپ کا ماتحت ہو وہ بھی آپ کی نبوت کی آخریت کو نہیں توڑتا.اسی طرح مسلمانوں کی طرف سے لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ (بخاری کتاب احادیث الانبیآء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل) والی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے.اگر اس کے یہ معنے کئے جائیں.کہ میری وفات کے بعد کوئی نبی نہیںآئے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے زمانہ میں کوئی نبی آسکتا تھا؟ جب آپ ساری دنیا کی طرف مبعوث کئے گئے تھے تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ آپ کے زمانہ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آسکتااور جب آپ کے زمانہ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آسکتا تھا تو پھر یہ کہنا کہ میری وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیا مفہوم رکھتا تھا.دراصل اس کا بھی یہی مفہوم تھا کہ میری نبوت پر کوئی ایسا زمانہ نہیں آسکتا جس میں وہ ختم ہو جائے اور یہ بالکل درست ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے.چنانچہ اگر ایک طر ف ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام تھے اور آپ کی شریعت کو جاری کرنے والے تھے.آپ کا کوئی علیحدہ کلمہ نہیں تھا کوئی علیحدہ نمازیں نہیں تھیں.چونکہ لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو بھول گئے تھے اس لئے خدا تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تارسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا آپ دوبارہ احیاء کریں.گویا یہ ظلّی نبوت ہے اور ظِلّ کوئی الگ وجود نہیں ہوتا بلکہ اصل چیز کا ہی عکس ہوتا ہے.پس لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کا بھی وہی مفہوم ہے جو مَسْجِدِیْ اٰخِرُ الْمَسَاجِدِ کا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس نبوت میں ہتک ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ میں آپ کی نبوت کو منسوخ کرتا ہوں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت میں ہتک ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ میں نے آپ سے کوئی فیضان حاصل نہیں کیا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت میں ہتک ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ اس نے براہ راست نبوت حاصل کی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت میں ہتک ہے جس کا مدعی یہ اعلان کرے کہ اس نے آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کو منسوخ کر دیا ہے خواہ وہ ان کو جزوی طور پر منسوخ کرے یا کلی طور پر منسوخ کرے.بلکہ
Page 201
اگر وہ آپ کا کوئی ایک حکم بھی بدلتا ہے تب بھی وہ آپ کی شریعت کو منسوخ کرنے والا ہے.اور لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ والی حدیث اسے جھوٹا قرار دیتی ہے.ایسے آدمی کو یقیناً ہم بھی کافر اور دجال کہیں گے اور اسے نبی چھوڑ ایک معمولی مسلمان بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے.بلکہ دوسرے مسلمانوں سے ہمارا جھگڑا ہی اس بات پر ہے کہ دوسرے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آخری زمانہ میں آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے.ہم کہتے ہیں کہ وہ مسیح موسوی سلسلہ کے نبی ہیں اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بغیر نبوت پائی ہے اس لئے ایسے نبی کے واپس آنے کا عقیدہ رکھنا جو آپ کا غلام نہیں آپ کی شدید ہتک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت بگڑی تو اس کی اصلاح کے لئے آپ کی امت میں سے تو کوئی شخص کھڑا نہ ہوا بلکہ دو ہزار سال پہلے کا نبی لانا پڑا.ایسا عقیدہ رکھنا یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرناک ہتک ہے.اس طرح محمدی سلسلہ کو موسوی سلسلہ کا دستِ نگر بننا پڑتا ہے جسے کوئی سچا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا.یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیّد وُلد آدم اور سید الانبیاء کہا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی اُمت بگڑے گی تو آپ کی امت کی اصلاح کے لئے باہر سے ایک نبی آئے گا جو موسوی سلسلہ کا ہو گا.اُمّت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہو گا جو ان مفاسد کی اصلاح کر سکے.یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی غنیم چڑھ کر آجائے تو کہا جائے کہ ہمارا بادشاہ بے شک طاقتور ہے مگر اس کے پاس کوئی فوج نہیں جو اس غنیم کا مقابلہ کر سکے اس لئے دوسرے بادشاہ سے فوج منگوائی جائے.حیرت آتی ہے کہ ان لوگوں کی عقلیں کس طرح ماری گئی ہیں اور وہ کس طرح یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت پر جب شیطان کا حملہ ہو گا تو اُ س کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کے پاس کوئی فوج نہیں ہو گی.ہاں موسوی سلسلہ کا ایک نبی عیسیٰ (علیہ السلام) آئے گا اور وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا اور اس طرح آپ کو اپنے احسان کے نیچے لائے گا.ہمارے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرناک ہتک ہے اور جس شخص کے دل میں ذرا بھی ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو وہ ایسا ظالمانہ عقیدہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتا.اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخر الانبیاء کے اگر یہ معنے کئے جائیں کہ آپ تمام نبیوں کے آخر میں آئے ہیں تو اس کے صرف اتنے معنے ہوں گے کہ آپ نبیوں کی قطار میں آخر میں کھڑے ہیں جیسے نیچے کے نقشہ سے ظاہر ہے.اللہ تعالیٰ....مختلف انبیاء....محمد رسول اللہ ؐ...انسان.اب ظاہر ہے کہ قطار میں جو آخری آدمی ہوتا ہے
Page 202
وہ دوسروں سے افضل نہیں ہوتا کہ اِسے کوئی خوبی کی بات سمجھا جائے.یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بہت سے سپاہی ایک قطار میں کھڑے ہوں تو ان میں سے جو آخری سپاہی ہو اس کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ وہ تمام سپاہیوں پر فضیلت رکھتا ہے کیونکہ وہ آخر میں کھڑا ہے حقیقتاً اسے کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو گی بلکہ وہ بھی دوسروں کی طرح ایک سپاہی ہوگا.اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر احمدیوں کے علماء کے قول کے مطابق قطار میں آخری نبی تسلیم کرلیا جائے تو اس سے آپ کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی.بلکہ آپ بھی دوسرے نبیوں کی مانند ایک نبی قرار پاتے ہیں.لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الانبیاء کہا گیا ہے مگر ایک اور حدیث ایسی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوّل الانبیاء کہا گیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے.آپ فرماتے ہیں کُنْتُ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ وَ اٰدَمُ مُنْجَدِلٌ فِیْ طِیْنِہٖ.میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی مٹی کے ڈلے میں پڑا ہوا تھا.گویا آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے خاتم النبیین تھے یادوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ آپ اوّل النبیین تھے.اب اگر غیر احمدی علماء کے قول کے مطابق آپ کو نبیوں کی قطار کے آخر میں مان لیا جائے تو آپ اوّل الانبیاء نہیں ہو سکتے اور اگر اوّل الانبیاء مانا جائے تو آخر الانبیاء نہیں ہو سکتے.لیکن ان دونوں حدیثوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور کشف کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو دونوں حدیثیں واضح ہو جاتی ہیں.یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوّل الانبیاء ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے اور آپ کا آخر الانبیاء ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے اور پھر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ سب انبیاء سے افضل ہیں.مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت آتی ہے.آپ فرماتے ہیں جب معراج ہوا تو میں پہلے آسمان پر گیا وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے.میں ان سے بھی اوپر نکل گیا اور دوسرے آسمان پر پہنچا.وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے میں ان سے بھی اوپر نکل گیا اور تیسرے آسمان پر پہنچا.وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے.میں ان سے بھی اوپر نکل گیا اور چوتھے آسمان پر گیا.وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے.میں ان سے بھی اوپر نکل گیا اور پانچویں آسمان پر پہنچا وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے میں ان سے بھی اوپر نکل گیا اور چھٹے آسمان پر پہنچا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے میں ان سے بھی اوپر نکل گیا اور ساتویں آسمان پر پہنچا وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تب جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا.اب اور اوپر چلیں.میں اوپر گیا اور سدرۃ المنتہیٰ میں جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی(مسند احمد بن حنبل مسند مالک بن صعصعہ).
Page 203
یہ سیر اِلَی اللہ اس نقشہ سے ظاہر ہو سکتی ہے.اللہ سدرۃ المنتہیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام اہل زمین اب اس نقشہ کو دیکھو تو مخلوق کے مقام پر جو شخص کھڑا ہو کر دیکھے گا اس کی نظر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی اور سب سے آخر اس کی نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑےگی.گویا سب نبیوں میں سے آخری نبی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے گا.اس طرح آپ کی یہ حدیث بھی درست ثابت ہو جاتی ہے کہ اَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِیَآءِ اور آپ دوسرے انبیاء سے بھی افضل ثابت ہو جاتے ہیں.آپ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں کیونکہ آپ ان سے بھی اوپر نکل گئے.آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ ان سے بھی اوپر نکل گئے.آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ ان سے بھی اوپر نکل گئے.آپ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ ان سے بھی اوپر نکل گئے.آپ حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ ان سے بھی اوپر نکل گئے.آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ ان سے بھی اوپر نکل گئے.آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ ان سے بھی اوپر نکل گئے.لیکن اگر اوپر کے نقشہ کو اللہ تعالیٰ کے مقام سے دیکھاجائے تو پھر سب سے اوّل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نظر آئے گا.آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا.پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا.پھر حضرت ہارون علیہ السلام
Page 204
کا.پھر حضر ت ادریس علیہ السلام کا.پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا.پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا.پس آپ آخر الانبیاء بھی ہیں اور آپ اوّل الانبیاء بھی ہیں.مگر انہی معنوں میں جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے.ورنہ پیدائش کے لحاظ سے آپ کُنْتُ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ وَ اٰدَمُ مُنْجَدِلٌ فِیْ طِیْنِہ کا مصداق کیوں کر ہو سکتے ہیں.ان معنوں کی رو سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی کہ اُوْتِیْتُ فَوَاتِـحَ الْکَلِمِ وَ جَوَامِعَہٗ وَخَوَاتِـمَہٗ (مسند احـمد بن حنبل مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص) حل ہوجاتی ہے کیونکہ سب سے اقرب مقام پر جس سے کلام ہوا یقیناً اسے فواتح الکلم ملے اور بندوں کی طرف سے جسے سب سے اوپر جا کر کلام ملا اسے خواتم الکلم ملے.کیونکہ باقی سب کلام اس سے نچلے مقام پر ہوئے ہیں اور چونکہ وہ ہر مقام پر سے گذر کر اوپر پہنچا اسے جوامع الکلم ملے.درحقیقت لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ اور اَنَا اٰخِرُ الْاَنْبِیَآءِ.یہ دو حدیثیں معراج کے واقعہ پر مبنی ہیں اور حدیثِ معراج ہی ان کو حل کرتی ہے.مگر مسلمانوں نے غلطی سے ان سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت بند ہے معلوم ہوتا ہے کہ خود صحابہ کو بھی احساس تھا کہ ختم نبوت کے بارہ میں لوگ افراط سے کام لیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زور دینے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکیں گے.چنانچہ اس بارہ میں مندرجہ ذیل حوالہ جات مفید روشنی ڈالتے ہیں.خاتم النبیین کے معنے صحابہؓ کے نزدیک اوّل.ابن ابی شیبہ سے در منثور میں ایک حدیث منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ ؓ نے صحابہ کو یہ کہتے سن لیا کہ اِنَّہُ خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ وَ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ.آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.آپ نے بڑے جوش سے فرمایا قُوْلُوْا خَاتَمَ النَّبِیِّیّنَ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو کہو مگر یہ مت کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.اب یہ ایک سیدھی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے تھے حضرت عائشہ ؓ ان کی تردید نہیں کر سکتی تھیں.یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ آپ تو کہیں لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ مگر حضرت عائشہؓ اس کی تردید فرمائیں اور کہیں وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ.حضرت عائشہ ؓ جیسے وجود سے اس چیز کا امکان ہی نہیں ہو سکتا.آپ کا مطلب درحقیقت یہی تھا کہ خاتم النبیین قرآن کریم کا لفظ ہے جس سے کوئی غلطی نہیں لگ سکتی.مگر لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ سے غلط فہمی ہو سکتی ہے.اس لئے خاتم النبیین تو بےشک کہو مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا.ورنہ ایک عارف تو سمجھ جائے گا کہ خَاتَمُ النَّبِیِّیْن اور لَانَبِیَّ بَعْدِیْ سے صرف اتنی مراد ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو میرے سلسلہ کو
Page 205
ختم کردے اور میری شریعت کو منسوخ کرے.مگر ایک عامی شخص یہ نتیجہ نکال لے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نبی بھی نہیں آسکتا جو آپ کا شاگرد ہو اور آپ کے دین کو قائم کرنے والا ہو.یہی وجہ تھی کہ باوجوداس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ.حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا قُوْلُوْا خَاتَمَ النَّبِیِّیّنَ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ.یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا.حضرت عائشہ ؓ کا لوگوں کو لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کہنے سے روکنا تاکہ وہ کسی غلط عقیدہ پر قائم نہ ہو جائیں بالکل ویسا ہی ہے جیسے احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اٹھ کر کہیں باہر تشریف لے گئے اور آپ کو واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی.صحابہ ؓ گھبرائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں.ان دنوں شام کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں عیسائی مدینہ پر حملہ نہ کر دیں.اس لئے صحابہ ؓ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو چنانچہ وہ ادھر اُدھر آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے.حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی تلاش کرتے کرتے ایک باغ کی طرف چلا گیا.دیکھا تو اس کا بڑا دروازہ بند تھا.مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں بلی کی طرح ایک سوراخ میں سے اندر گھس گیا.دیکھا تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے.میں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بہت گھبرا گئے تھے کہ نہ معلوم آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں.اب آپ کو دیکھا ہے تو جان میں جان آئی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.ابو ہریرہ ؓ جاؤ اور جو بھی تم سے ملے اسے کہو مَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْـجَنَّۃَ.جو بھی لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوجائے گا.حضرت ابو ہریرہ ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ.اتنی بڑی بات کون مانے گا آپ مجھے اپنی کوئی نشانی دے دیں.آپ نے اپنی جوتیاں انہیں دےدیں.جب وہ دروازے سے نکلے تو حضرت عمر ؓ آرہے تھے.حضرت ابو ہریرہ ؓ نے انہیں دیکھتے ہی کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مجھے جو بھی ملے میں اسے یہ خوشخبری سنا دوں کہ مَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْـجَنَّۃَ.حضرت عمر ؓ نے یہ سنتے ہی ان کے سینہ پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا تم لوگوں کا ایمان خرا ب کرنا چاہتے ہو.حضرت ابو ہریرہ ؓ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو عمر ؓ نے مار ڈالا.آپ ہی نے فرمایا تھا کہ جو تم سے ملے اسے کہہ دو کہ مَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْـجَنَّۃَ.مگر عمر ؓ سے میں نے کہا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا.اتنے میں حضرت عمر ؓ بھی تشریف لے آئے.انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ جو لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں.حضرت عمر ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح تو کمزور
Page 206
لوگ عمل چھوڑ دیں گے.آپ نے فرمایا بہت اچھا اعلان روک دو(مسلم کتاب الایـمان باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الـجنۃ قطعًا).گویا خود ہی ایک بات کہی اور پھر خود ہی فرما دیا کہ اس کی اشاعت نہ کرو.بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خوشخبری حضرت عمر ؓ کے متعلق ہی تھی اور چونکہ یہ بات ان کو پہنچ گئی اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اور لوگوں کو یہ بات نہ کہو مگر یہ درست نہیں.درحقیقت اس کا مخاطب ہر مومن تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص سچے دل سے لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے اور پھر اس پر عمل کرے وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خدا کو بھی مانے اور پھر اس کے احکام پر عمل بھی نہ کرے اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر کوئی شخص صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہے تو وہ ضرور جنتی ہو گا.یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف منہ سے لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہہ دینے سے انسان جنت میں چلا جاتاہے جیسے آج کل مسلمان خیال کرتے ہیں کہ منہ سے لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہہ دیا تو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں.بہر حال لوگوں کی غلط فہمی کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے حضرت عمر ؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ لوگ نقلی معنوں کو لے لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب کسی عمل کی ضرورت نہیں.اس پر آپ نے خود ہی اس سے روک دیا.اسی طرح حضرت عائشہ ؓ نے بھی خیال کیا کہ کہیں لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ سے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام میں بڑے آدمی پیدا ہی نہیں ہوں گے اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے.چنانچہ آپ نے لَا نَبِیَّ بَعْدِی کہنے سے روک دیا اور خَاتَمَ النَّبِیِّیْن چونکہ قرآن کریم کا لفظ تھا اور اس سے کوئی دھوکا نہیں لگ سکتا تھا آپ نے فرمایا تم خاتم النبیین بے شک کہو مگر یہ مت کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ ؓ یقین رکھتی تھیں کہ کلی طور پر نبوت کا انقطاع تسلیم کرنا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے.ورنہ اگر ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہوتا تو پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ حالانکہ یہ الفاظ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں.آپ نے اسی لئے یہ کہا کہ آپ کے نزدیک خاتم النبیین کے الفاظ زیادہ محفوظ تھے اور غلط فہمی کا امکان ان میں کم تھا اور پھر قرآنی الفاظ تھے.پس آپ نے کہا کہ یہ لفظ بولا کرو اور دوسرے الفاظ یعنی لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ ایسے ہیں کہ جو ایک معنوں سے ٹھیک ہیں لیکن بعض دوسرے معنوں سے ان کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے اس لئے ان لفظوں کو عام طور پر استعمال نہ کیا کرو.اس روایت پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہیں تو حضرت عائشہ ؓ کو روکنے کا کیا حق تھا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ ؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا علم نہ ہو گا اس وجہ سے انہوں نے منع کیا اور اس قسم کا عدم علم کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہوا کرتا.
Page 207
حضرت عائشہ ؓ کا لوگوں کو لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ کہنے سے روکنا تاکہ وہ کسی غلط عقیدہ پر قائم نہ ہو جائیں بالکل ویسا ہی ہے جیسے احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اٹھ کر کہیں باہر تشریف لے گئے اور آپ کو واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی.صحابہ ؓ گھبرائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں.ان دنوں شام کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں عیسائی مدینہ پر حملہ نہ کر دیں.اس لئے صحابہ ؓ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو چنانچہ وہ ادھر اُدھر آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے.حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی تلاش کرتے کرتے ایک باغ کی طرف چلا گیا.دیکھا تو اس کا بڑا دروازہ بند تھا.مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں بلی کی طرح ایک سوراخ میں سے اندر گھس گیا.دیکھا تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے.میں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو بہت گھبرا گئے تھے کہ نہ معلوم آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں.اب آپ کو دیکھا ہے تو جان میں جان آئی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.ابو ہریرہ ؓ جاؤ اور جو بھی تم سے ملے اسے کہو مَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْـجَنَّۃَ.جو بھی لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوجائے گا.حضرت ابو ہریرہ ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ.اتنی بڑی بات کون مانے گا آپ مجھے اپنی کوئی نشانی دے دیں.آپ نے اپنی جوتیاں انہیں دےدیں.جب وہ دروازے سے نکلے تو حضرت عمر ؓ آرہے تھے.حضرت ابو ہریرہ ؓ نے انہیں دیکھتے ہی کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مجھے جو بھی ملے میں اسے یہ خوشخبری سنا دوں کہ مَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْـجَنَّۃَ.حضرت عمر ؓ نے یہ سنتے ہی ان کے سینہ پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا تم لوگوں کا ایمان خرا ب کرنا چاہتے ہو.حضرت ابو ہریرہ ؓ دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو عمر ؓ نے مار ڈالا.آپ ہی نے فرمایا تھا کہ جو تم سے ملے اسے کہہ دو کہ مَنْ قَالَ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْـجَنَّۃَ.مگر عمر ؓ سے میں نے کہا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا.اتنے میں حضرت عمر ؓ بھی تشریف لے آئے.انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ جو لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں.حضرت عمر ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح تو کمزور لوگ عمل چھوڑ دیں گے.آپ نے فرمایا بہت اچھا اعلان روک دو(مسلم کتاب الایـمان باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الـجنۃ قطعًا).گویا خود ہی ایک بات کہی اور پھر خود ہی فرما دیا کہ اس کی اشاعت نہ کرو.بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خوشخبری حضرت عمر ؓ کے متعلق ہی تھی اور چونکہ یہ بات ان کو پہنچ گئی اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اور لوگوں کو یہ بات نہ کہو مگر یہ درست نہیں.درحقیقت اس کا مخاطب ہر مومن تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص سچے دل سے لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہے اور پھر اس پر عمل کرے وہ ضرور جنت میں داخل ہو گا.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خدا کو بھی مانے اور پھر اس کے احکام پر عمل بھی نہ کرے اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر کوئی شخص صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ کہے تو وہ ضرور جنتی ہو گا.یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف منہ سے لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہہ دینے سے انسان جنت میں چلا جاتاہے جیسے آج کل مسلمان خیال کرتے ہیں کہ منہ سے لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہہ دیا تو پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں.بہر حال لوگوں کی غلط فہمی کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے حضرت عمر ؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ لوگ نقلی معنوں کو لے لیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب کسی عمل کی ضرورت نہیں.اس پر آپ نے خود ہی اس سے روک دیا.اسی طرح حضرت عائشہ ؓ نے بھی خیال کیا کہ کہیں لَا نَبِیَّ بَعْدِیْ سے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام میں بڑے آدمی پیدا ہی نہیں ہوں گے اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے.چنانچہ آپ نے لَا نَبِیَّ بَعْدِی کہنے سے روک دیا اور خَاتَمَ النَّبِیِّیْن چونکہ قرآن کریم کا لفظ تھا اور اس سے کوئی دھوکا نہیں لگ سکتا تھا آپ نے فرمایا تم خاتم النبیین بے شک کہو مگر یہ مت کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ ؓ یقین رکھتی تھیں کہ کلی طور پر نبوت کا انقطاع تسلیم کرنا اسلامی تعلیم کے خلاف ہے.ورنہ اگر ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہوتا تو پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ لَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ حالانکہ یہ الفاظ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں.آپ نے اسی لئے یہ کہا کہ آپ کے نزدیک خاتم النبیین کے الفاظ زیادہ محفوظ تھے اور غلط فہمی کا امکان ان میں کم تھا اور پھر قرآنی الفاظ تھے.پس آپ نے کہا کہ یہ لفظ بولا کرو اور دوسرے الفاظ یعنی لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ ایسے ہیں کہ جو ایک معنوں سے ٹھیک ہیں لیکن بعض دوسرے معنوں سے ان کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے اس لئے ان لفظوں کو عام طور پر استعمال نہ کیا کرو.اس روایت پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے ہیں تو حضرت عائشہ ؓ کو روکنے کا کیا حق تھا.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ ؓ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا علم نہ ہو گا اس وجہ سے انہوں نے منع کیا اور اس قسم کا عدم علم کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہوا کرتا.اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امر تو قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کے بارہ میں کثرت سے احادیث موجود ہیں اور صرف ایسے ہی مسائل سے صحابہ کی ناواقفیت فرض کی جا سکتی ہے جن کا علم چند لوگوں میں محدود ہو.مگر یہ تو ایسے مسائل میں سے نہیں.اس لئے اس وجود کو اس سے ناواقف قرار دینا جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھا دین اس سے سیکھو.درست نہیں.نیز الفاظ روایت بتاتے ہیں کہ ایک جماعت کو حضرت عائشہ ؓ نے یہ ارشاد فرمایا ہے یا یہ کہ وہ اکثر ایسا فرمایا کرتی تھیں اور یہ امر فرض کرنا اور بھی مشکل ہے کہ حضرت عائشہ ؓ کی یہ رائے لوگوں میں پھیلی اور کسی نے بھی ان کی رائے کو ردّ نہ کیا.پس معلوم یہی ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ ؓ اس علم کے باوجود کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے ان الفاظ کے عام استعمال سے روکتی تھیں تا لوگوں میں غلط فہمی نہ ہو جائے.یہ اعتراض کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے کو کون روک سکتا ہے درست نہیں کیونکہ الفاظ سے نہیں روکا جاتا بلکہ ان کے بے موقع استعمال سے روکا جاتا ہے جیسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر ؓ مَنْ قَالَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ دَخَلَ الْـجَنَّۃَ کہنے سے روکتے ہیں.اس لئے تو نہیں کہ وہ فقرہ غلط تھا.عمرؓ اسے غلط کہنے والے کون تھے بلکہ اس لئے کہ وہ ایسے الفاظ میں تھا کہ سمجھ دار آدمی تو اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں لیکن عوام کے متعلق خطرہ تھا کہ وہ غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے.یہی مطلب حضرت عائشہ ؓ کا تھا.دوسری روایت بھی ابن ابی شیبہ سے ہے اس کے الفاظ یہ ہیں قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ الْمُغِیْرَۃِ ابْنِ شُعْبَۃَ صَلَّی اللہُ عَلٰی مُـحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ یعنی حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس کسی شخص نے یہ الفاظ کہے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام و درود بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے اور جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا فَقَالَ الْمُغِیْرَۃُ حَسْبُکَ اِذَا قُلْتَ خَاتَمَ الْاَنْبِیَاءِ مغیرہ بن شعبہ ؓ نے فرمایا کہ جب تو نے خاتم الانبیاء کہہ دیا تھا تو یہ کافی تھا لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ کہنے کی ضرورت نہیں تھی فَاِنَّا کُنَّا نُـحَدِّثُ اَنَّ عِیْسیٰ عَلَیہِ السَّلَامُ خَارِجٌ.کیونکہ ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ؑظاہر ہونے والے ہیں فَاِنْ ھُوَ خَرَجَ فَقَدْ کَانَ قَبْلَہٗ وَ بَعْدَہٗ.پس اگر وہ نکل آئے تو وہی آپ کے پہلے بھی ہوں گے اور آپ کے پیچھے بھی ہوں گے.(الدر المنثور الاحزاب:۴۰) اس حدیث سے یہ امور ظاہر ہیں.(۱)مغیرہ بن شعبہ کے نزدیک خاتم النبیین کے الفاظ کے یہ معنے نہیں تھے کہ آپ کے بعد نبی نہیں آسکتا.(۲)ان کے نزدیک لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ کے الفاظ ویسے محفوظ نہیں جیسے خاتم النبیین کے الفاظ محفوظ ہیں.(۳) مغیرہ بن شعبہ کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان تھا.(۴)وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زند ہ آسمان پر ہونے کے قائل نہ تھے.تبھی آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے.بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کُنَّا نُـحَدِّثُ اَنَّ عِیْسیٰ عَلَیہِ السَّلَامُ خَارِجٌ.ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ زمین سے ظاہر ہوں گے معلوم ہوتا ہے ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں مگر وہ پھر زندہ کر کے واپس بھجوائے جائیں گے اس لئے انہوں نے نَازِلٌ مِّنَ السَّمَاءِ نہیں کہا بلکہ خَارِجٌکا لفظ استعمال کیا ہے.
Page 208
تھا.(۴)وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زند ہ آسمان پر ہونے کے قائل نہ تھے.تبھی آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے.بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں کُنَّا نُـحَدِّثُ اَنَّ عِیْسیٰ عَلَیہِ السَّلَامُ خَارِجٌ.ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ زمین سے ظاہر ہوں گے معلوم ہوتا ہے ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں مگر وہ پھر زندہ کر کے واپس بھجوائے جائیں گے اس لئے انہوں نے نَازِلٌ مِّنَ السَّمَاءِ نہیں کہا بلکہ خَارِجٌکا لفظ استعمال کیا ہے.تیسری روایت ابن الانباری نے کتاب المصاحف میں بیان کی ہے کہ عبد الرحمان اسلمی کہتے ہیں کُنْتُ اُقْرِءُ الْـحَسَنَ وَالْـحُسَینَ میں حضرت حسن اور حسین کو قرآن کریم پڑھانے پر مقرر کیا گیا تھا فَمَرَّ بِیْ عَلِیٌّ ابْنُ اَبِیْ طَالِبٍؓ ایک دن میرے پاس سے حضرت علی ابن ابی طالبؓ گذرے اَنَا اُقْرِءُھُمَا خَاتِمَ النَّبِیِّیْنَ بِکَسْـرِ التَّاءِ.اور میں انہیں خاتم النبیین بکسر التاء پڑھا رہا تھا جس کے معنے ختم کرنے والے کے ہوتے ہیں فَقَالَ لِیْ اَقْرِئْـھُمَا وَ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ بِفَتْحِ التَّائِ وَ اللہُ الْمُوَفِّقُ.حضرت علی ؓ نے یہ سن کر فرمایا تم میرے بیٹوں کو خاتم النبیین بکسر التاء نہ پڑھاؤ بلکہ بفتح التاء پڑھاؤ اللہ توفیق عطا فرمائے.یہ حضرت علی ؓ کا فتویٰ ہے کہ خاتم النبیین کی بکسر التاء والی قرأت بفتح التاء والی قرأت کے تابع ہے.لیکن علماء کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کی بفتح التاء والی قرأت بکسر التاء والی قرأت کے تابع ہے اگر خاتم کے وہ معنے ہوتے جو علماء لیتے ہیں تو حضرت علی ؓ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ عبد الرحمان اسلمی آپ کے بیٹوں کو بکسر التاء پڑھا رہے ہیں مگر آپ فرماتے ہیں میرے بیٹوں کو بکسر التاء نہ پڑھاؤبفتح التاء پڑھاؤ.اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ کے نزدیک خاتم النبیین بفتح التاء کے الفاظ زیادہ محفوظ تھے.یوں بکسر التاء بھی جائز ہے لیکن چونکہ اس سے ڈر ہو سکتا تھا کہ کہیں حضرت حسنؓاور حضرت حسینؓیہ نہ سمجھ لیں کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گاخواہ وہ آپ کا شاگرد ہی کیوں نہ ہو.اس لئے آپ نے استاد سے کہا کہ میرے بیٹوں کو بفتح التاء پڑھاؤ بکسر التاء نہ پڑھاؤ.اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی ؓ کے نزدیک خاتم النبیین کے وہ معنے نہیں تھے جو بکسر التاء سے نکلتے ہیں یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا.ورنہ آپ بکسر التاء پڑھانے سے استاد کو منع نہ فرماتے.چوتھی حدیث جس سے اس پر روشنی پڑتی ہے یہ ہے.ابن ماجہ اور ابن مندہ میں روایت درج ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓنے بیان کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آپ نے فرمایا لَوْ عَاشَ لَکَانَ صِدِّیْقًا نَّبِیًّا (ابن ماجۃ کتاب الـجنائز باب ماجاء فی الصلٰوۃ علی ابن رسول اللہ و ذکر وفاتہ)
Page 209
اگر ابراہیم زندہ رہتا تو وہ ضرور نبی ہوتا.یہاں علماء کو بہت مشکل پیش آئی ہے کیونکہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا تو پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور نبی ہوتا.اس مشکل کو حل کرنے کے لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو اس لئے وفات دے دی کہ وہ نبی نہ ہو جائیں اور آیت خاتم النبیین پوری ہو.مگر یہ درست نہیں.اگر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے تو دنیا کا ہر شخص نبی ہونا چاہیے کیونکہ تمام حضرت آدمؑ کی اولاد ہیں اگر حضرت آدمؑ کو نبی نہ کہا جائے تب بھی دنیا میں نصف یا چوتھائی تو ضرور نبی ہونے چاہئیں.کیونکہ اکثر بنی آدم حضرت نوح کی اولاد سے ہیں.بلکہ بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق تو ساری دنیا ہی حضرت نوحؑ کی اولاد سے ہے.اسی طرح اگر یہ اصل درست ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو نبی ہونا چاہیے تھا لیکن ہمیں تو ان میں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا.اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے.پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے نبی کیوں نہ بنے.بلکہ آپ کی وفات کے بعد تو یہ بات عام طور پر مشہور ہو گئی تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.اگر آپ کی اولاد نے نبی بننا ہوتا تویہ کیوں کہا جاتا.پس یہ کہنا کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے واقعات کے خلاف ہے.پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا تھا اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ اگر ابراہیم زندہ رہا تو نبی بن جائے گا.اس لئے خدا تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی تاکہ وہ نبی نہ بن سکیں مگر یہ بھی نہایت غیر معقول بات ہے کیونکہ جو چیز ہونی ہی نہ تھی اس کے لئے اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے درست ہی نہیں ہو سکتے تھے.آخر نبوت جبکہ طبعی امر نہیں بلکہ شرعی امر ہے اور اس کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو پھر ابراہیم کس طرح نبی ہو سکتے تھے.اگر خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ آپؐکے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو وہ نبی کسی طرح بن جاتے.وہ خواہ زندہ بھی رہتے نبی نہیں بن سکتے تھے.پس یہ بالکل غلط ہے کہ ابراہیم کو اس لئے وفات دی گئی کہ وہ کہیں نبی نہ بن جائیں.بلکہ وہ قانون قدرت کے مطابق فوت ہو ئے اور پیشگوئی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ بعد میں ظاہر ہونے والے واقعات کے مطابق تھی نہ کہ اس کو پورا کرنے کے لئے واقعات پیدا کئے گئے گوبعض دفعہ واقعات پیشگوئی کی خاطر پیدا بھی کئے جاتے ہیں.بہر حال اس حدیث سے امکان نبوت ثابت ہے ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم یہ کبھی نہ فرماتے کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور نبی بنتا.
Page 210
سُورۃُ الْکَافِرُوْنَ مَکِّیَّۃٌ سورۂ کافرون.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ سَبْعُ اٰیَاتٍ مَّعَ الْبَسْمَلَۃِ اور بسم اللہ سمیت اس کی سات آیات ہیں سورۃ کافر ون مکی سورۃ ہے ابن مسعودؓ کے نزدیک سورۃ کافرون مکی ہے اور حسن اور عکرمہ بھی یہی کہتے ہیں.ابن عباس اور قتادہ اور ضحاک اور ابن زبیر کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے(فتح البیان تعارف سورۃ الکافرون) ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اور مغرب کی نماز میں چوبیس ۲۴ دفعہ پڑھی ہے(مسند احـمد بن حنبل مسند عبد اللہ بن عـمر رضی اللہ عنہ).مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دوسری کتب میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے.میرے نزدیک چوبیس سے مراد چوبیس نہیں بلکہ کثرت مراد ہے.اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کثرت سے فجر کی نماز میں لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے وہاں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے.جیسے سورۃ کافرون اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.مسند حاکم میں ابی ابن کعبؓسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وتر کی تین رکعتوں میں سے پہلی میں سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى دوسری میں قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور تیسری میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھا کرتے تھے (المستدرک للحاکم کتاب التفسیر تفسیر سورۃ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ) سورۃ کافرون قرآن مجید کے چوتھے حصے کے برابر ہے حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ قرآن شریف کے تیسرے حصہ کے برابر ہے اور قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ قرآن کے چوتھے حصہ کے برابر ہے(ترمذی ابواب فضائل القراٰن باب ماجاء فی اِذَا زُلْزِلَتِ......) اور آپ کئی دفعہ صبح کی دو رکعتوں میں یہ دو سورتیں پڑھا کرتے تھے.(یہ روایت طبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں نقل کی ہے ) اس حدیث کا بھی یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ہے اور چوتھے حصہ کے برابر قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ہے.کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو باقی قرآن کے نازل ہونے کی
Page 211
ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ صداقتیں اپنی جڑ کے لحاظ سے بہت مختصر ہوتی ہیں.مثلاً اگر مذہب کا خلاصہ نکالا جائے تو اتنا ہی ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے محبت اور بندوں سے شفقت یہی قرآن کریم سے اور حدیثوں سے دین کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے.اب اگر کوئی شخص کہہ دے کہ بندوں پر شفقت آدھا دین ہے تو اس کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ اس فقرہ کے بعد آدھے دین کی ضرورت نہیں ر ہتی اور نہ یہ کہنے سے کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑی اہم چیز ہے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دین کے نصف حصہ کا ذکر ہو گیا.اب اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں.پس قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ کو ثلث قرآن قرار دینا یا قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کو ربع قرار دینے کے معنے یہی ہیں کہ ان کے مطالب نہایت اہم ہیں.اور اگر ان کے مطالب پر صحیح طور پر غور کیا جائے تو دین کی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں.مثلاً قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ میں توحید پر زور ہے حقیقت یہی ہے کہ توحید مذہب کی جان ہے اگر کوئی شخص توحید کو اچھی طرح سمجھ لے تو مذہب کا بہت سا حصہ اس پر روشن ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت اسے مذہب کی بہت سی تفصیلات کی طرف خود راہنمائی کر دیتی ہے.اسی طرح قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ میں مذہب پر استقلال کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس میں بھی کیا شبہ ہے کہ سچائی کے مان لینے سے سچائی پر قائم رہنا کم اہم نہیں.جتنی خرابی دنیا میں سچائی کے نہ ماننے سے پیدا ہوتی ہے اتنی ہی یا اس سے زیادہ خرابی سچائی پر قائم نہ رہ سکنے سے پیدا ہوتی ہے.اسلام آیا لوگوں نے اس کو قبول کیا.خدا نے اس کی طاقت اور قوت کو ظاہر کیا.وہ دنیا کے کناروں میں پھیل گیا.باوجود اس کے کہ دنیا کے نصف سے زیادہ حصہ نے ابھی اسے تسلیم نہیں کیا تھا وہ ساری دنیا پر غالب آگیا اور بظاہر کوئی چیز اس کو کمزور کرنے والی باقی نہیں رہی تھی مگر پھر وہ سمٹ سمٹا کر بقول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چلاگیا(بخاری کتاب التفسیر سورۃ الجمعۃ باب قولہ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا...) آخر یہ کیوں ہوا؟ اس لئے نہیں کہ عیسائیت نے اسلام کو کوئی شکست دی.اس لئے نہیں کہ یہودیت نے اسلام کو کوئی شکست دی.اس لئے نہیں کہ بدھ مذہب نے اسلام کو کوئی شکست دی یا ہندو مذہب نے اسلام کو کوئی شکست دی.بلکہ محض اور محض اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اسلام پر قائم رہنے سے غفلت برتی اور ایک لباس پارینہ کی طرح اس کو اتار کر پھینک دیا.اگر مسلمان اسلام پر قائم رہتے تو آج ساری دنیا مسلمان ہوتی.اور مسلمانوں کی جو بے کسانہ حالت اس وقت نظر آتی ہے اس کی بجائے وہ غالب اور مقتدر وجود نظر آتے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وجہ سے اس سورۃ کو ربع قرآن قرار دیا تو بالکل سچ فرمایا.حقیقت یہ ہے کہ اگر آ پ اس سے بھی زیادہ اس سورۃ کی اہمیت قرار دیتے تب بھی درست ہوتا.
Page 212
مسند احمد حنبل، مسند ابو داؤد اور سنن ترمذی اور سنن نسائی میں لکھا ہے.نوفل بن معاویہ الاشجعی نے ایک دن کہایارسول اللہ مجھے وہ بات سکھائیے جو میں بستر پر لیٹتے وقت کہا کروں قَالَ اِقْرَاْ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ثُمَّ نَمْ عَلٰی خَاتِـمَتِـھَا فَاِنَّـھَابَرَاءَ ۃٌ مِّنَ الشِّـرْکِ(تـرمذی کتاب الدعوات باب ماجاء فیمن یقرأُ القراٰن عند المنام) آپ نے فرمایا قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ پڑھا کرو اور پھر اس کے آخری حصہ کو پڑھتے پڑھتے سو جایا کرو.کیونکہ اس میں شرک سے بیزاری کا ذکر ہے.اس حدیث سے بھی میرے اس استدلال کی تصدیق ہوتی ہے جو میں نے اوپر کیا ہے.مومن کا یہ پختہ ارادہ کہ وہ کبھی بھی باطل کو قبول نہیں کرے گا اور خواہ کچھ ہوجائے وہ سچ کو نہیں چھوڑے گا ایک حیرت انگیزطاقت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے.اگر اس کی بجائے لوگ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے سابق خیالات یا اپنے باپ دادا کے خیالات کو نہیں چھوڑیں گے یامولویوں کے خیالات کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر ان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا.اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان جن خیالات پر سوتا ہے وہ بہت مضبوطی کے ساتھ اس کے ذہن میں راسخ ہو جاتے ہیں.اسلام ہی ہے جس نے یہ نکتہ سب سے پہلے بیان کیا ہے مگر مسلمان ہی ہیںجو اس نکتہ کو بھول گئے ہیں.انسانی دماغ صرف اسی وقت کسی چیز کو نہیں سوچتا جب وہ اس کے کان میں کہی جاتی ہے بلکہ جب بھی وہ فارغ ہوتا ہے وہ اس پر عقلی جگالی کرتا رہتا ہے.اسی وجہ سے بچہ کی پیدائش کے وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس وقت تم اپنے دنیوی کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹو تو اور تمام باتوں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کچھ دعائیں پڑھا کرو اور انہی کو سوچتے سوچتے سو جایا کرو.اس میں اسی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ رات کے وقت انسان کا دماغ فارغ ہوتا ہے اس وقت وہ دن کی باتوں کو دہراتا ہے اور اسی وجہ سے بعض دفعہ ایسے واقعات کے متعلق انسان کو خواب آجاتے ہیں جو دن کے وقت اس نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں.یا ایسے خیالات کے متعلق انسان کو رات کے وقت خواب آجاتے ہیں جو دن کے وقت اس کے دل میں گذرے ہوتے ہیں یا ایسے نظاروں کے متعلق اسے خواب آجاتے ہیں جو دن کے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے سے گذرے ہوتے ہیں.اگر انسان سوتے وقت بعض اعلیٰ قسم کی دعائیں اور تسبیح اور تحمید کے کلمات دہراتے ہوئے اور سوچتے ہوئے سو جائے تو یقیناً اس کے دماغ میں رات کے فارغ اوقات میں وہی خیالات اور وہی باتیں گھومتی رہیں گی.نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک لمبے عرصہ تک ان خیالات کے دماغ میں گھومنے کی وجہ سے وہ جڑ پکڑ جائیں گے اور مضبوطی سے قائم ہو جائیں گے اور آسانی سے نکالے نہیں جا سکیں گے.اور انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور اس کو استقلال کی توفیق ملے گی.
Page 213
طبرانی اور ابو یعلیٰ نے حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے کہ ’’قَالَ رَسُوْلُ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا اَدُلُّکُمْ عَلٰی کَلِمَۃٍ تُنْجِیْکُمْ مِنَ الْاِشْـرَاکِ بِاللہِ تَقْرَءُوْنَ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ عِنْدَ مَنَامِکُمْ ‘‘یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تم کو اللہ تعالیٰ کے شرک سے بالکل بچا لے.وہ بات یہ ہے کہ سوتے وقت تم قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ پڑھو.یہ حدیث بھی میرے اوپر کے استدلال کی تائید کرتی ہے.ابن مردویہ نے زید بن علقم سے روایت کی ہے کہ جو شخص دو۲سورتیں لے کر خدا تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گا اس سے کوئی حساب نہیں لیاجائے گااور وہ دو سورتیں قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ہیں(فتـح البیان تعارف سورۃ الکافـرون).اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو شخص توحید پر قائم ہو گا اور استقلال سے اس پر قائم رہے گا جو ان دونوں سورتوں کا مضمون ہے تو وہ ہر ایک حساب سے بالا ہو گا.طبرانی، بزار اور ابن مردویہ نے خباب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تو قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ پڑھا کرتے تھے(فتـح البیان تعارف سورۃ الکافـرون) (یعنی ساری سورۃ)اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ لیٹیں اور قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کی ساری کی ساری سورۃ نہ پڑھیں.صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کی دونوں سورتیں طواف کی دونوں رکعتوں میں بھی پڑھا کرتے تھے.مسندا حمد حنبل میں حضرت عبد اللہ بن عمر ؓ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہینہ پورا صبح کی دونوں رکعتوں میں قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ پڑھتے دیکھا ہے.اس سورۃ کے فضائل کے متعلق جُبیر بن مطعم سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتُـحِبُّ یَاجُبَیْـرُ اِذَا خَرَجْتَ سَفْرًا اَنْ تَکُوْنَ اَمْثَلَ اَصْـحَابِکَ ھَیْئَۃً وَاَکْثَرَھُمْ زَادًا یعنی اے جبیرؓ کیا تم پسند کرتے ہو کہ جب تم سفر کے لئے نکلو تو اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ شان تمہارے چہرہ سے ٹپک رہی ہو اور سب سے زیادہ زاد راہ تمہارے ساتھ ہو.جبیر ؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ! اس پر آپ نے فرمایا تب تم سفر میں یہ پانچ سورتیں پڑھا کرو یعنی سورۃ الکافرون سے لے کر قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ تک(کنزل العمال کتاب السفر باب اٰداب السفر ).سورۃ الکافرون سے آخر تک چھ سورتیں ہیں پس یا تو پانچ کے یہ معنے ہیں کہ سورہ ٔ تَبَّتْ کو اس گنتی میں سے آپ نے نکال دیا ہے اور یا پھر الکافرون کے بعد کی سورتوں کو آپ نے پانچ قرار دیا ہے یا پانچ
Page 214
راوی کی غلطی ہے اور مراد یہ ہے کہ الکافرون سمیت چھ یا الکافرون کو نکال کر اس کے بعد کی پانچ سورتیں.پھر آپ نے فرمایا جب پڑھنا شروع کرو تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھ کر تلاوت شروع کیا کرو (یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ہر سورۃ کا حصہ ہے ) جبیرؓ کہتے ہیں کہ میں مال دار نہ تھا اور جب میں سفر کرتا تھا تو سب ساتھیوں سے برا حال میرا ہوتا تھا.اور سب سے کم زاد میرے پاس ہوتا تھا.مگراس کے بعد ان سورتوں کی برکت کی وجہ سے میرا حال سب ساتھیوں سے اچھا ہو گیا اور سب سے زیادہ زاد میرے پاس ہوتا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم کی سورتوں کے پڑھنے میں برکات ہیں.جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل نازل کرتا ہے مگر اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان سورتوں میں زیادہ تر غیر مذاہب کا مقابلہ ہے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور مصائب کے وقت میں استقلال قائم رکھنے کی تلقین ہے اور توحید پر زور دیا گیا ہے اور باہمی لڑائی اور جھگڑے سے روکا گیا ہے.اور جب انسان ان مضامین کو بار بار اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے اندر یہ خصلتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اور ان خصلتوں کی وقعت اور اہمیت بھی اس پر ثابت ہوتی چلی جاتی ہے.اور جب وہ ان خصلتوں پر عمل کرتا ہے تو غیروں کی نگاہ میں معزز ہو جاتا ہے اور اپنوں کی نگاہ میں اتحاد کا باعث بن جاتا ہے جب بھی غیر دیکھیں کہ یہ شخص ہمارے حالات سے مرعوب ہو گیا ہے تو ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی قوم کی عزت ان کی نظروں سے گر جاتی ہے.۱۹۲۴ء میں مَیں انگلستان تبلیغِ اسلام کے مواقع دیکھنے کے لئے گیا تھا.میں نے اس وقت وہی لباس پہنے رکھا جو میں ہندوستان میں پہنتا تھا اور یوروپین لوگ نہ صرف یہ کہ اس لباس کو ذلیل سمجھتے ہیں بلکہ چونکہ ان کا رات کا لباس ایسا کھلا ہوتا ہے جیسے ہماری قمیص اور سلوار.اس لئے وہ ہماری قمیص اور سلوار کو رات کا لباس سمجھتے ہیں.یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ ہمیں اس لباس میں ننگا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ رات کے لباس میں دوسروں کے سامنے نہیں آتے.ایک دن ہمارے مبلغ انچارج میرے پاس آئے اور بڑی تشویش سے کہنے لگے کہ آپ کے اس لباس کی وجہ سے یہاں لوگوں کو بہت ٹھوکر لگ رہی ہے.آپ اگر پتلون نہیں پہن سکتے تو کم سے کم علی گڑھ فیشن کا گرم پاجامہ پہن لیں اور قمیص کو اس کے اندر ٹھونس لیا کریں.میں نے ان سے پوچھا کہ آخر میں ایسا کیوں کروں.ان لوگوں کو میرے قومی لباس پر اعتراض کرنے کا حق کیا ہے؟مبلغ صاحب نے کہا کہ حق ہو یانہ ہو بہر حال اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے اور ہماری قومی تحقیر ہوتی ہے.اسی دن مجھ سے ملنے کے لئے لنڈن کے اورینٹل کالج کے پرنسپل۱ سر ڈینی سن راس
Page 215
اور کچھ اور بڑے بڑے آدمی آئے.میں نے ان کے سامنے یہی سوال رکھا اور کہا کہ کیا آپ لوگ اس لباس کو ذلیل سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ یوروپین تہذیب ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے.ہم آپ کے لباس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں.میں نے سمجھ لیا کہ محض مغربی تہذیب کے نتیجہ میں یہ ایسا کہہ رہے ہیں.ان کے دل میں یہ بات نہیں.میں نے پھر اصرار سے کہا کہ آپ میرے دوست ہیں سچ سچ بتائیے کہ آپ کی قوم پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ سچی بات تو یہی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس لباس میں لوگوں کے سامنے آنے کو برا سمجھتے ہیں اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں.سر ڈینی سن راس علی گڑھ اور کلکتہ میں بھی پروفیسر رہ چکے تھے.میںنے ان سے پوچھا کہ سر ڈینی سن آپ یہ بتائیے کہ جب آپ ہمارے ملک میں تھے تو کیا سلوار یا دھوتی پہنا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں.میں نے کہا تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آ پ ہمارے ملک میں جا کر اپنا ہی لبا س رکھیں تو حرج نہیں اور ہم آپ کے ملک میں آکر اپنا لباس رکھیں تو یہ بری بات ہے.کیا اس کے یہ معنے نہیں بنتے کہ آپ اپنی قوم کو بڑا سمجھتے ہیں اور ہماری قوم کو ذلیل سمجھتے ہیں.اس لئے آپ ہم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں جس مطالبہ کو انہی حالات میں آپ پورا کرنے کے لئے تیار نہیں.اور جب یہ بات ہے تو ایک ہندوستانی کی قومی غیرت کب برداشت کر سکتی ہے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لئے اپنے لباس کو بدل لے.پھر میں نے ان سے کہا کہ سچ سچ بتائیے جب ایک ہندوستانی کوٹ اور پتلون پہنتا ہے تو آپ کا دل خوش نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری قومی برتری کو تسلیم کر لیا ہے اور ہمارے لباس کو اختیار کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ معین صورت میں یہ خیال آئے یا نہ آئے لیکن دماغ کے پسِ پردہ تو یہ خیال ضرور ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے.میں نے کہا اس سے دوسرے لفظوں میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا لباس آپ کے ملک میں نہیں چھوڑتا آپ کو اس پر غصہ بھی آتا ہے.آپ اپنی ہتک بھی محسوس کرتے ہیں.لیکن آپ کے دماغ کے پس پردہ یہ خیال بھی رہتا ہے کہ یہ شخص ہم سے اور ہماری تہذیب سے ڈرا نہیں.اس پر وہ کچھ کھسیانے سے ہو کر کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے.تب میں نے ان سے کہا کہ میں ہندوستان سے چلتے ہوئے یہاں کی سردی کا خیال کر کے گرم کپڑے کے ایسے پاجامے سلوا کر اپنے ساتھ لایا تھا جو علی گڑھ فیشن کے ساتھ ملتے تھے.وہ دیکھنے میں پتلون نما معلوم ہوتے ہیں گو ان کے اندر ازار بند استعمال ہوتا ہے لیکن اب میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گا اور اسی طرح واپس لے جاؤں گا کیونکہ میں انگریز کے ہندوستان پر حاکم ہوجانے کی وجہ سے نہ اپنے ملک کے لوگوں کو انگریز سے کمتر سمجھتا ہوں اور نہ اپنے ملک کی تہذیب کو اس کی تہذیب سے کمتر سمجھتا ہوں اور انگریزی تہذیب اور اس کے تمدن کی نقل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں.
Page 216
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبیر ؓسے یہ بات فرمائی کہ تم یہ سورتیں پڑھو تو تمہارا رعب بڑھ جائے گا.اس سے درحقیقت اسی طرف اشارہ تھا کہ ان سورتوں میں اسلام کی مرکزی تعلیم کو پیش کیا گیا ہے اور اس پر مخالفت کے باوجود مستقل رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور جو شخص بھی مخالفانہ ماحول میں اپنے خیالات پر قائم رہنے کی جرأت دکھائے گا لازماً وہ اپنی اور اپنی قوم کی عزت قائم کر دے گا اور یہ جو فرمایا کہ اس سے تمہارا زادِ راہ بڑھ جائے گا.اس میں بھی درحقیقت اسی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص دوسروں کے آگے سرنگوں ہونے سے انکار کر دے گا اسے یہ کبھی خیال نہیں آئے گا کہ کوئی میری خبر گیری کرے گا اور میری مدد کرے گا اور جب وہ لوگوں کی امداد کے خیال سے اپنے خیالات کو آزاد کر لے گا تو لازماً وہ حلال روزی اور باعزت روزی کے لئے کوشش بھی کرے گا.کاش ہمارے نوجوان مغربی ممالک کی طرف سفر کرتے ہوئے یا ان ملکوں میں سفر کرتے ہوئے ان سورتوں کو پڑھیں اور ان کے مضمون پر غور کریں تو یقیناً وہ کفر کی طاقتوں سے کبھی متاثر نہ ہوں اور اپنی بے بسی اور اپنی ذلت اور اپنی قوم کی کمتری کا احساس ان کے دلوں سے جاتا رہے.حق یہ ہے کہ انسان ظاہری حالات سے اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا کہ وہ اپنی شکست خوردہ ذہنیت سے متاثر ہوتا ہے.حالات کی کمزوری کو بڑی آسانی سے بدلا جا سکتا ہے لیکن شکست خوردہ ذہنیت کو بدلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے.ایشیا کی گری ہوئی مالی حالت میں بھی لاکھوں لکھ پتی اور کروڑ پتی موجود ہیں لیکن شکست خوردہ ذہنیت سے محفوظ بہت کم لوگ ہیں.باوجود یوروپ کے شدید مقابلہ کے دولت تو ہم نے کما لی لیکن اپنی ذہنیت کو ان کے حملہ سے محفوظ نہیں کر سکے اور یہی شکست خوردہ ذہنیت ہے جس کی اصلاح کی طرف ان سورتوں میں توجہ دلائی گئی ہے اور جس کا سامان ان سورتوں میں پیدا کیا گیا ہے.سورۃ کافرون کا ایک اور نام اصمعی کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ کے لوگ (یعنی تابعی اور صحابہ ؓ)کہا کرتے تھے کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص مُقَشْقِشَتَانِ ہیں (یعنی یہ سورتیں نفاق سے بچانے والی ہیں اور قوت ایمانیہ پیدا کرنے والی ہیں )اور ابو عبیدہ ؓ کہتے تھے کہ جس طرح رال کھجلی کو دور کر کے تندرست کر دیتی ہے اسی طرح یہ سورتیں انسان کو شرک سے صحت بخشتی ہیں.(قرطبی تعارف سورۃ الکافرون) وقتِ نزول نولڈکے کا خیال ہے کہ یہ سورۃ مکی زندگی کے پہلے دَور کے آخری زمانہ کی ہے یعنی چوتھے سال کے قریب کی.اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ اسی وقت محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار سے بحث کرنے کے قابل ہوئے تھے.کیونکہ مسلمانوں اور مشرکوں میں بحث اور مجادلہ کے ابتدائی زمانہ کے بعد دونوں فریق کے اصولی خیالات متعین ہو گئے تھے اور وہی وقت درحقیقت مذہبی بحث کا ہوتا ہے.
Page 217
نولڈکے کا یہ خیال اس حد تک ٹھیک ہے کہ کسی مذہب کے ابتدائی زمانہ میں چونکہ اس کے پیش کردہ خیالات کی جدت کی وجہ سے اس کے منکرین اس کی حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھتے اس لئے اس مذہب کے متعلق بحث محض سطحی ہوتی ہے.آہستہ آہستہ تبادلہ خیالات کے بعد نئے مذہب کے ماننے والے بھی اپنی باتوں کو ایک معین صورت میں پیش کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور مخالفین بھی اپنے پراگندہ خیالات کو ایک معین صورت دے دیتے ہیں.پس ایک جدید تحریک جو ایک سابقہ شکستہ تحریک کی جگہ لینے کے لئے پیدا ہوتی ہے اس کے اعلان کے چند سال بعد لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ زیادہ معین اور مشخص صورت میں دونوں قسم کے خیالات کا جائزہ لے سکیں اور اندازہ کر سکیں.اور چونکہ اس سورۃ میں ایک قطعی چیلنج اپنے مخالفین کو دیا گیا ہے.اس لئے نولڈکے اس اندرونی شہادت کی بنا پر یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ سورۃ پہلے دور کے آخری زمانہ کی ہے.ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا نزول حالات کے تابع نہیں بلکہ وہ تو اصولی ضرورت کو دیکھتا ہے.بدیوں کا ردّ کرتا ہے اور نیکیوں کی تفصیل بیان کرتا ہے.لیکن باوجود اس خیال کے ظاہر کرنے کے ہم اس سورۃ کے متعلق تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں کہ جہاں تک اس کے چیلنج کا سوال ہے وہ اسی وقت دیا گیا ہو جبکہ اسلام کے مخالف اس چیلنج کو قبول کرنے اور سمجھنے کے قابل ہو گئے ہوں.پس اس سورۃ کے متعلق ہمیں اس بات کے تسلیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں کہ نولڈکے کے خیال کے مطابق اگر تاریخ کی شہادت اس کے خلاف نہ ہو تو یہ سورۃ چوتھے سال کے شروع میں یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہو.کیونکہ وہی وقت تھا جبکہ مخالف اسلام کے دعویٰ کو ایک معین صورت میں اپنے ذہنوں میں لانے کے قابل ہو گئے اور اس کے مقابلہ میں اپنے مذہب کے بھی کوئی معین اصول انہوں نے طے کر لئے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر کسی نہ کسی رنگ میں اس سے صلح کرنے کا خیال ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگا(گو جیسا کہ ہم آگے چل کر بتائیں گے اس سورۃ کا صرف اتنا ہی مضمون نہیں ہے بلکہ اس سورۃ میں بہت زیادہ وسیع مطالب پائے جاتے ہیں.مگر یہ بعید نہیں کہ اس کے ایک مضمون کی وجہ سے اس کے مناسب ِ حال وقت پر اس سورۃ کا نزول ہو گیا ہو)بہرحال نولڈکے مستشرقین میں سے ایک بہت بڑی اہمیت رکھنے والا شخص ہے بلکہ مستشرقین کا سردار سمجھاجاتا ہے.پس مستشرقین کو اس بات کے ماننے سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کی اپنی جماعت کے اصول کے مطابق یہ سورۃ چوتھے یا حد سے حد پانچویں سال کے شروع میں نازل ہوئی ہے اور یہ امر تسلیم کرلینے کے بعد سورہ ٔ نجم کے متعلق جو روایات وہ نقل کرتے ہیں ان کی تردید آپ ہی آپ ہو جاتی ہے.کیونکہ سورہ ٔ نجم پانچویں سال یا اس کے بعد کی ہے.پس لازماً سورہ ٔ کافرون اس سے پہلے کی ہے.اور اگر سورۃ نجم سورہ ٔ کافرون
Page 218
سے بعد کی ہے جیسا کہ ہمارا بھی یقین ہے اور جیسا کہ مستشرقین کے تسلیم کردہ اصول کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہے تو پھر کوئی عقلمند یہ بات کس طرح مان سکتا ہے کہ مشرکین کے جس مطالبہ کا ردّ سور ہ ٔ کافرون میں قطعی طور پر کر دیا گیا تھا سورہ ٔ نجم میں اسی مطالبہ سے متاثر ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کوئی ایسے الفاظ جاری ہو گئے جو کہ شرک کی کسی قدر تائید کرتے تھے.نعوذباللہ من ذالک.غرض اس سورۃ کے وقت ِ نزول کے متعلق جو مستشرقین نے بحث کی ہے وہ سورہ ٔ نجم کے مشہور واقعہ کی تردید کے لئے ایک بہت بڑا ثبو ت بہم پہنچا دیتی ہے.ترتیب یہ سورۃ اپنے محل کے لحاظ سے جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں آخری زمانہ کے متعلق معلوم ہوتی ہے.کیونکہ پہلی سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی.پس گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہیں لیکن زور آئندہ زمانہ کے متعلق ہے.اس سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ میں کفر پھر اسلام پر غالب آجائے گا اور جہاں تک مادی حالات کا سوال ہے اسلام قریباً قریباً ختم ہو جائے گا.لیکن اس وقت پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دوبارہ دنیا میں کسی اپنے مثیل اور شاگرد کے ذریعہ سے ظاہر ہو گی اور دنیا کو پھر وہی چیلنج دے گی جو پہلے آپ نے دیا تھا اور کہے گی کہ خواہ کتنا زور لگا لو میں کفر سے مغلوب نہیں ہوں گا اور کفر کی باتوں کو تسلیم نہیں کروں گا.یہ وہی زمانہ ہے جس کو مہدی یا مسیح کا زمانہ کہا جاتا ہے اور جس وقت دجال یا یاجوج وماجوج نے یعنی عیسائیت کے مذہبی اور سیاسی ظہور نے اسلام پر غلبہ پانا تھا اور بظاہر اسلام کی شان و شوکت کو مٹاکر عیسائیت کی حکومت کو مستحکم طور پر قائم کر دینا تھا.یہ سورۃ بتاتی ہے کہ جہاں عام طور پر مسلمان مغربی خیالات سے متاثر ہو کر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیں گے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح غیر اسلامی خیالات کے آگے ہتھیار ڈالنے سے کلی طور پر انکار کر دے گی اور باوجود اس کے کہ تشدّد اور زبردستی سے اس زمانہ میں اسلام بالکل کام نہیں لے گا پھر بھی وہ کفر پر غالب آجائے گا اور انسانوں کے دل کفر و الحاد سے پاک ہو کر پھر اسلام کی طرف راغب ہو جائیںگے.اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے ایک قریب کا تعلق بھی ہے پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے انعامات نازل کئے جائیں گے.ایسے بڑے بڑے انعام جن کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک نئے آدم کی حیثیت کے طور پر دنیا میں پیش کرے گا جس کے مقابلہ میں اس کے دشمنوں کی نسل تباہ ہو جائے گی اور صرف آپ کی نسل باقی رہ جائے گی.سورۂ کافرون میں اللہ تعالیٰ اس پہلی سورۃ کے مضمون کی
Page 219
طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ ؐ کے منکرو!تم اتنے بڑے انعامات کو دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوتے تو اتنا تو سوچو کہ محمد رسول اللہ ؐاور ان کے اتباع کے متعلق تم یہ کس طرح خیال کر سکتے ہو کہ تمہارے واہی اور کمزور عقائد اور تمہاری بے دلیل باتوں سے متاثر ہو کر وہ اپنادین چھوڑ دیں گے.اگر وہم اپنے مقام کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تو مشاہدہ اپنے مقام کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے.پس تمہاری یہ سب کوششیں خلاف عقل ہیں.ان حالات میں تو تم کو خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے تھا.اور خدا تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرنا چاہیے تھا.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَۙ۰۰۲ (ہم ہر زمانہ کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ )تُو(کفار سے )کہتا چلا جا (کہ) سُنو اے کافرو! لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَۙ۰۰۳ میں تمہارے طریق عبادت کے مطابق عبادت نہیں کرتا.وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُۚ۰۰۴ اور نہ تم میرے طریق عبادت کے مطابق عبادت کرتے ہو.وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ۰۰۵ اور نہ میں (ان کی )عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے چلے آئے ہو.وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُؕ۰۰۶ اور نہ تم (اس کی)عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں.تفسیر.اَلْکٰفِرُوْنَ سے مراد ہر زمانہ کے کافر ہو سکتے ہیں اَلْکٰفِرُوْنَ سے مراد
Page 220
خاص کافر بھی ہو سکتے ہیں اور سارے کافر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہوں یا بعد کے زمانہ کے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور جیسا کہ اوپر کے نوٹ سے ظاہر ہے اس جگہ دونوں ہی باتیں بیان کی گئی ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے کفار کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور آپ کے زمانہ کے بعد آنے والے کفار کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور مکہ کے کفار کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے جن کا زور آخری زمانہ میںہونا تھا.پس اس آیت میں اَلْکٰفِرُوْنَ کے دونوں ہی معنے ہیں یہ بھی معنے ہیں کہ اے مکہ کے کافرو! میں تم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہوں اور یہ معنے بھی ہیں کہ اے قیامت تک کے کفار! خصوصاً زمانہ آخر کے کفار! جن کے زمانہ میں پھر اسلام کمزور ہو کر ان کے رحم و کرم تلے آچکا ہوگا میں تم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتا ہوں.لفظ قُلْ کہنے میں حکمت قُلْ کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تُو ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہہ دے.حالانکہ اس آیت کے الفاظ وسیع ہیں اور اس میں مخاطب آئندہ زمانہ کے لوگ بھی ہیں.صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ مراد نہیں ہیں.اس سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی شخصیت بروزی طور پر بار بار دنیا میں ظاہر ہوگی.اگر خدا تعالیٰ بندوں سے خطاب کرتا تب تو اور بات تھی لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ تُو ہر زمانہ کے لوگوں سے یہ کہہ دے یہ ایک واضح اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ ہر زمانہ میں دنیا میں ظاہر ہوتی رہے گی.کبھی چھوٹے پیمانہ پر کبھی بڑے پیمانہ پر.اسی کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے کہ اِنَّ اللہَ یَبْعَثُ لِھٰذِہِ الْاُمَّۃِ عَلٰی رَأْسِ کُلِّ مِائَۃِ سَنَۃٍ مَنْ یُّـجَدِّدُ لَھَا دِینَـھَا(ابوداؤد کتاب الملاحـم باب ما یذکر فی قرن المائۃ) یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر سو سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارہ میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا.یہ قُلْ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے.گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروںگا اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دُھل دُھلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا.مسیحؑ اور مہدی کے زمانہ میں یہ بات زیادہ نمایاں طور پر ہونے والی ہے کیونکہ اس زمانہ کے متعلق بہت بڑے فتنوں کی پیشگوئی ہے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَا بُعِثَ نَبِیٌّ اِلَّا قَدْ اَنْذَرَ اُمَّتَہُ الدَّجَّالَ (ابو داؤد کتاب الملاحـم باب خروج الدجال ) یعنی جب سے دنیا پیدا
Page 221
ہوئی ہے تمام انبیاء نے دجال کے فتنہ سے اپنی امت کو ڈرایا ہے.یا حرف ِ نداء ہے اورجب اس کے بعد الف لام تعریف کا آئے تو چونکہ تعریف کے الف لام کا ہمزہ وصلی ہوتا ہے اور یا کو اس کے ساتھ جوڑنے میں عرب غرابت محسوس کرتا ہے اس لئے یا اور اس الف لام کے درمیان اَیُّـھَا کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے.بعض نحویوں نے توصرف اتنی ہی غرض اس کی بتائی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس میں ھا کی وجہ سے ایک زائد معنے تنبیہ کے بھی پیدا ہو جاتے ہیں.مگر بہرحال تنبیہ ہو یا نہ ہو عرب لوگ یا کے بعد تعریف کے الف لام سے پہلے اَیُّـھَا کا لفظ بڑھا دیتے ہیں.صرف لفظ اَللّٰہُ سے پہلے اَیُّـھَا کا لفظ نہیں بڑھایا جاتا حالانکہ اس سے پہلے بھی الف لام ہے.اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ میں جو الف لام ہے وہ تعریف کا الف لام نہیں بلکہ اسم ذات کا حصہ ہے.جو لوگ اَیُّـھَا کو تاکید کے معنوں میں لیتے ہیں وہ اس جگہ پر یہ معنے کرتے ہیں ’’سُن رے اے شخص‘‘یا ’’سنو رے ! اے لوگو‘‘گویا عام محاورہ کے رو سے تو يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کے معنے ہوں گے.’’اے تمام کے تمام کافرو! خواہ وہ عرب کے ہو یا کسی اور ملک کے یا اس زمانہ کے ہو یا آئندہ کسی زمانہ میں آنے والے ہو.‘‘لیکن اَیُّھَا کو تنبیہ کے معنوں میں قرار دے کر اس کے یہ معنے بن جائیں گے کہ اے کفار خواہ تم کسی زمانہ سے تعلق رکھتے ہو کان کھول کر سن رکھو.اَلْکٰفِرُوْنَ.کَفَرَ کے معنے انکار کے ہوتے ہیں خواہ و ہ کسی چیز کا انکار ہو.قرآن کریم میں یہ لفظ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى (البقرۃ:۲۵۷) جو لوگ شیطانوں اور شیطانی لوگوں کی باتیں ماننے سے قطعی طور پر انکار کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لے آتے ہیں وہ ایک مضبوط چٹان پر قائم ہوجاتے ہیں.اور قرآن کریم میں یَکْفُرُوْنَ بِاللّٰہِ (النسآء:۱۵۱) بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں.پس جہاں تک اس لفظ کے ظاہر کا تعلق ہے یہ نہ برا ہے نہ اچھا ہے.اصل معنے تو اس کے ڈھانپ دینے کے ہوتے ہیں.بدی کا ڈھانپنا بھی کفر کہلائے گااور نیکی کا ڈھانپنا بھی کفر کہلائے گا.بدی کا چھپانا بھی کفر کہلائے گا اور نیکی کا چھپانا بھی کفر کہلائے گا.لیکن چونکہ کثرت سے قرآن کریم میں یہ لفظ نیکی کے انکار کے متعلق استعمال ہوا ہے.اس لئے جب کسی قرینہ کے بغیر یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے برے ہی لئے جاتے ہیں جس طرح مومن کے معنے بھی ایسے ہی ہیں لیکن وہ زیادہ تر نیکی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.اس لئے جب مومن کا لفظ بغیر قرینہ کے استعمال ہو تو اس کے معنے ہمیشہ نیک کے لئے جائیں گے.حالانکہ قرآن کریم میں مومن کا لفظ بھی برے معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ فرماتا ہے
Page 222
یُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ (النسآء:۵۲) وہ شیطان اور شیطانی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں.اور یہ جو قرآنی استعمال ہے یہ بلاوجہ نہیں اس کے اندر بھی حکمت ہے.چنانچہ ایمان کے لفظ میں گو ماننے کے معنے پائے جاتے ہیں لیکن اصل معنے اِیْـمَان کے امن دینے اور برکت دینے کے ہیں.اور امن اور برکت اچھے لفظ ہیں.پس چونکہ ابتدائی معنوں کے لحاظ سے یہ لفظ اچھا ہے اس لئے اکثر طور پر اسے اچھے ہی معنوں میں استعمال کیاجاتا ہے اورجب کوئی اس کے ساتھ قرینہ نہ ہو تو اس کے اچھے ہی معنے سمجھے جاتے ہیں.اس کے مقابلہ میں کفر کے معنے چھپا دینے کے ہیں اور چھپانے کا مفہوم اپنی ذات میں اچھا مفہوم نہیں ہوتا.کیونکہ یہ برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ بالخاصہ اکثر برائی ہی چھپائی جاتی ہے.پس جب تک کوئی خلاف قرینہ نہ ہو یہ لفظ اپنے اصلی معنوں کے لحاظ سے برے ہی معنوں میں سمجھاجائے گا ہاں قرینے کے ساتھ کبھی اس کے اچھے معنے بھی ہو جائیں گے.پس لفظ ِ کُفر بغیر قرینے کے برا ہے اور لفظ ِ ایمان بغیر قرینہ کے اچھا ہے گو دونوں ہی بری یاا چھی نسبت کے ساتھ الٹ معنے بھی دے دیتے ہیں.(الف)اس جگہ پر اَلْکَافِرُوْنَ کے معنے تمام مفسرین نے کفار مکہ کے کئے ہیں.چنانچہ علامہ سیوطی نے دُرّ منثور میں ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورۃ مکہ کے مشرکوں کے بعض سوالات کے جواب میں نازل ہوئی تھی.علامہ شوکانی جو فتح القدیر کے مصنف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ الف لام اس جگہ پر جنس کا آیا ہے یعنی تمام کافروں کی طرف اشارہ ہے لیکن مراد وہ کفار مکہ ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارہ میں کچھ سوالات کئے تھے اور جو کفر کی حالت میں مر ے.علامہ ابن جریر بھی اپنی تفسیر جامع البیان میں یہی لکھتے ہیں کہ اس کے معنے یہ ہیں کہ قُلْ یَا مُـحَمَّدُ لِـھٰٓـؤُلَٓاءِ الْمُشْـرِکِیْنَ الَّذِیْنَ سَاَلُوْکَ.یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)ان مشرکوں سے جنہوں نے تجھ سے بعض سوالات کئے ہیں یوں کہہ دے.تفسیر روح البیان میں شیخ اسمٰعیل حقی بروسوی لکھتے ہیں وَ ھُمْ کَفَرَۃٌ مَّـخْصُوْصَۃٌ.اور وہ لوگ جن کا اس آیت میں ذکر ہے وہ ایک مخصوص جماعت کفار کی ہے جن کے متعلق یہ فیصلہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے.پھر آگے لکھتے ہیں فَلَا یَرِدُ اَنَّ مُقْتَضٰی ھٰذَا الْاَمْرِ اَنْ یَّقُوْلَ کُلُّ مُسْلِمٍ ذٰلِکَ لِکُلِّ جَـمَاعَۃٍ مِّنَ الْکُفّارِ.یعنی اس آیت کا مخصوص ہونا یہ لازمی نہیں قرار دیتا کہ ہم اس کا مخاطب ہر مسلمان کو نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہرمسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر قسم کے کافر کو یہ بات کہہ دے.(سورۃ الکافرون زیر آیت ا تا ۳)
Page 223
علامہ آلوسی اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں قَالَ اَجَلَّۃُ الْمُفَسِّـرِیْنَ اَلْمُرَادُ بِـھِمْ کَفَرَۃٌ مِّنْ قُرَیْشٍ مَـخْصُوْصُوْنَ قَدْ عَلِمَ اللہُ تَعَالٰی اَنَّـھُمْ لَا یَتَاَتّٰی مِنْـھُمُ الْاِیْـمَانُ اَبَدًا.یعنی تمام بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اَلْکَافِرُوْنَ سے مراد قریش کے وہ کافر ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے.علامہ قرطبی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھتے ہیں الف لام یہاں معہود ذہنی کے لئے آیا ہے یعنی ایسے کفار جن کا ذکر ذہن میں موجود ہے اور اگر اس کو جنس کے لئے سمجھا جائے تب بھی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کفار جن کے متعلق خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ کافر ہی مریں گے.پس یہ مخصوص معنوں پر دلالت کرتا ہے جس کا ذکر عام الفاظ میں آیا ہے.(تعارف سورۃ الکافرون) ماوردی نے بھی لکھا ہے کہ عُـنِیَ بِالْکٰـفِـرِیْنَ قَوْمًا مُعَیِّنِیْنَ لَا جَـمِیْعَ الْکٰفِرِیْنَ.یعنی اَلْکٰفِرِیْنَ کے لفظ سے ایک معین جماعت مراد ہے نہ کہ سارے کفار.لِاَنَّ مِنْـھُمْ مَنْ اٰمَنَ فَعَبَدَ اللہَ کیونکہ ان کفار میں سے بعض ایمان بھی لے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وَ مِنْـھُمْ مَنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ عَلٰی کُفْرِہٖ اور ان میں سے بعض ایسے تھے جومر گئے یا کفر کی حالت میں قتل کئے گئے اور وہی اس قول يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کے مخاطب ہیں.(تفسیر القرطبی تعارف سورۃ الکافرون) علامہ زمخشری اپنی تفسیر کشّاف میں لکھتے ہیں.اَلْمُخَاطَبُوْنَ کَفَرَۃٌ مَّـخْصُوْصَۃٌ قَدْ عَلِمَ اللّٰہُ مِنْـھُمْ اَنَّـھُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ.مخاطب اس آیت کے چند مخصوص کفار ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے.(اَلْکَافِرُوْنَ آیت ۱) علامہ محمد ابن حیّان اپنی تفسیر البحر المحیط میں لکھتے ہیں وَالْکٰفِرُوْنَ نَاسٌ مَّـخْصُوْصُوْنَ اور کفار سے اس جگہ پر مراد کچھ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے آ پ سے سوالات کئے تھے.(سورۃ الکافرون) ان حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین مکہ کے متعلق ہے اور مشرکین مکہ بھی سارے کے سارے مخاطب نہیں بلکہ ان میں سے ایک خاص جماعت مخاطب تھی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کئے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خاص دلالتوں کی وجہ سے یا سیاق و سباق کی وجہ سے ایک عام لفظ کو خاص معنوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور قرآن کریم میں ایسی مثالیں موجود ہیں.لیکن بلاوجہ ایسا کرنا جائز نہیں کیونکہ اس کے یہ معنے ہو جاتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے معنوں کومحدود کرتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں
Page 224
اس کے وسیع مطالب کو تنگ دائرہ میں لے آتے ہیں اور اس کے سمندر کو ایک چھوٹا دریا بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو قرآن کریم کی خدمت نہیں بلکہ اس سے دشمنی ہے.پس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہو کہ اس جگہ پر ہم ان وسیع معنوں کو جو لغت اور محاورہ قرآن کے لحاظ سے ثابت ہیں محدود کر سکیں.لغت کے لحاظ سے کافر کے معنے انکار کرنے والے کے ہوتے ہیں اور اس میں مشرک یا غیر مشرک.مکی یا غیر مکی کا کوئی امتیاز نہیں کیا جاتا.ہرشخص جو کسی بات کا انکار کرے کافر کہلائے گا.اور اَلْکٰفِرُوْن سے مراد وہ تمام کے تما م لوگ ہوں گے جو منکرین میں شامل ہوں گے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زبان عربی کے محاورہ کے مطابق بلکہ قریباً ہر زبان کے محاورہ کے مطابق کبھی الفاظ بظاہر حد بندی ظاہر کرتے ہیں لیکن معنوں میں عمومیت ہوتی ہے اور کبھی الفاظ عمومیت ظاہر کرتے ہیں لیکن معنوں میں محدودیت ہوتی ہے اور یہ طریق استعمال اختصار کی وجہ سے اختیار کیاجاتا ہے مثلاً کبھی ہم کسی ایک شخص کو ذہن میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریر ہمیشہ سزا پاتا ہے.ہمارے لفظ عام ہوتے ہیں لیکن مراد کوئی خاص شخص ہوتا ہے.اسی طرح کبھی ہم کسی جھوٹے کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اب تم ذلیل ہو جاؤ گے.لیکن مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر جھوٹ بولنے والا ذلیل ہوتا ہے اس لئے وہ بھی ذلیل ہو جائے گا.پس مخصوص کو عام کر دینا اور عام کو مخصوص کر دینا یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو قریباً ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے.بلکہ یہ زبان کا ایک لازمی حصہ ہے اگر اس طریق کو استعمال نہ کیاجائے تو بعض چھوٹے چھوٹے مضمونوں کے لئے بڑے بڑے فقرے اور بڑی بڑی عبارتیں استعمال کرنی پڑیں.بے شک غلط فہمی کا امکان ہو سکتا ہے لیکن عبار ت کا سیا ق وسباق یا کلام کا موقعہ اور محل غلطی کے امکان کو دور کر دیتا ہے.قرآن کریم میں بھی یہ طریق استعمال کیا گیا ہے لیکن اصول فقہ کے علماء نے عام اصول یہ رکھا ہے کہ گو عام الفاظ سے خاص جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے اور خاص جماعت سے عام جماعت بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن غالب قاعدہ یہ ہو گا کہ عمومیت کو خصوصیت کے اوپر فائق سمجھا جائے گا.یعنی جب ایک مضمون عام ہے تو مخصوص الفاظ کی وجہ سے اس کو مخصوص جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جائے گا بلکہ باوجود مخصوص الفاظ کے اس کے مضمون کو عام قرار دیا جائے گا اور اس سے دلیل پکڑی جائے گی.لیکن عام الفاظ کو مخصوص کرنے کے لئے نہایت واضح قرینہ قویہ کی ضرورت ہوگی اور بغیر کسی زبردست دلیل کے اس عام مضمون کو محدود نہیں کیا جا سکے گا.چنانچہ علامہ سیوطی اپنی کتاب اتقان میں لکھتے ہیں کہ اِخْتَلَفَ اَھْلُ الْاُصُوْلِ ھَلِ الْعِبْرَۃُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ.اَوْ بِـخُصُوْصِ السَّبَبِ وَالْاَصَـحُّ عِنْدَنَا الْاَوَّلُ.(الاتقان النوع التاسـع معرفۃ سبب النزول ) یعنی اصول فقہ کے علماء نے اس بارہ میں
Page 225
اختلاف کیا ہے کہ الفاظ کی عمومیت کی وجہ سے معنے بھی عام لئے جائیں گے یا جو مخصوص سبب کلام کا موجب ہوا ہوگا اس کی وجہ سے معنوں کو مخصوص کر دیا جائے گا.پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہی درست ہے کہ اگر لفظ عام ہوں تو خواہ سبب خاص ہو معنے عام ہی لئے جائیں گے خاص سبب کی وجہ سے معنوں کومحدود نہیں کیا جائے گا.شیخ محمد الخضری پروفیسر تاریخ اسلامی جامعہ مصری لکھتے ہیں اَلْعَامُ اِذَا وَرَدَ اُخِذَ عَلٰی عُـمُوْمِہٖ اِلَّا اِذَا قَامَ دَلِیلُ التَّخْصِیْصِ وَھُوَ الْمُخَصِّصُ.یعنی جب الفاظ عام ہوں تو معنے بھی عام ہی لئے جائیں گے سوائے اس کے کہ تخصیص کی کوئی دلیل ہو اور اگر ایسا ہو تومعنے اس تخصیص کی دلیل کی وجہ سے مخصوص ہو جائیں گے نہ کہ الفاظ کی وجہ سے.(کتاب اصول فقہ ص۲۴۱) لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے یہ بات ہی درست ہے کہ بعض جگہ مضمون عام ہوتا ہے لیکن بات ایک خا ص گروہ کے متعلق ہوتی ہے اور بعض جگہ پر ایک خاص گروہ کو مخاطب کیا ہوتا ہے لیکن مضمون تمام لوگوں پر منطبق ہوتا ہے بشرطیکہ ایسا کرنے پرکوئی قرینہ دلالت کرتا ہو.اس لئے ہم ان مفسرین کو جنہوں نے اس آیت کو خاص قوم یا خاص افراد پر منطبق کیا ہے اگر ان کے پاس دلیل ہو غلطی پر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ چیز جائز ہے اور قرآن کریم میں بھی مستعمل ہے اور دنیا کی باقی زبانوں میں بھی مستعمل ہے.پس اصل سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آیا اس سورۃ کے متعلق کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس کی وجہ سے ہم يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کے الفاظ کو ایک محدود جماعت کی طرف منسوب کر دیں اور عمومیت سے اس کو خارج کر دیں.سو اس کے سمجھنے کے لئے پہلے ہم خود قرآنی عبارت کو لیتے ہیں.اس سورۃ میں يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کے الفاظ لکھے گئے ہیں اور قرآن کریم میں غیر مشرکوں کو بھی کافر قرار دیا گیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (البیّنۃ:۲) اس آیت میں کافر کا لفظ جس طرح مشرکوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے اسی طرح یہود و نصاریٰ اور باقی کفار کے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے.پس قرآنی محاورہ کے رو سے اَلْکٰفِرُوْن کا لفظ عام ہے خاص نہیں.اب ہم مضمون کو لیتے ہیں تو اس سورۃ کی اگلی آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ نہ تو میں اس چیز کی عبادت کروں گا جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم اس چیز کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں.ظاہر ہے کہ یہ مضمون بھی عام ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ؓ صرف بتوں ہی کی پوجا سے پرہیز نہیں کرتے تھے بلکہ عبادت کے اس مفہوم سے بھی پرہیز کرتے تھے جو یہود اور نصاریٰ اور دوسر ے اہل مذاہب میں پایا جاتا تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہود کے طریقہ پر نماز نہیں پڑھی، کبھی عیسائیوں کے طریقہ پر نماز نہیں پڑھی، نہ یہوداور نصاریٰ نے کبھی اسلام کے
Page 226
طریقہ پر نماز پڑھی.پس اس آیت میں جو یہ امر بیان کیا گیا ہے کہ نہ تم میرے طریق پر عبادت کرو گے نہ میں تمہارے طریق پر عبادت کروں گا.یا یہ کہ نہ تم میرے معبود کی عبادت کروگے نہ میں تمہارے معبود کی عبادت کروں گا جیسے مشرکین مکہ پر منطبق ہوتا ہے ویسے ہی باقی دنیا کے کفار پر بھی منطبق ہوتا ہے.کیونکہ اوّل تو اسلام کے سوا کوئی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں جو توحید کامل کو پیش کرتا ہو.اگر ظاہری رنگ میں توحید کسی مذہب میں پائی بھی جاتی ہے تو وہ مذہب بھی صفات ِالٰہیہ کے بیان کرنے میں قرآن کریم سے بہت اختلاف رکھتا ہے.مثلاً یہودی مذہب خدا کو اس رنگ میں پیش کرتا ہے کہ وہ صرف یہودی نسل کے لوگوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہے.کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمان کسی صورت میں بھی اس خدا کی پرستش کرسکتے تھے جس کے متعلق یہ یقین کیا جائے کہ اس نے بنو اسرائیل کو اپنی پیاری قوم قرار دے لیا تھا اور بنو اسرائیل اور دوسری قوموں کے ساتھ سلوک میں و ہ امتیاز اور فرق سے کام لیتا تھا.ایسے خدا کی پرستش کے تو صاف معنے یہ تھے کہ اسلام جھوٹا ہے کیونکہ اس کا بانی غیر اسرائیلی تھا.اسی طرح مجوسی مذہب جو کہ یقیناً اہل کتاب میں سے ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی صفات کی تشریح میں بہت اختلاف رکھتا تھا.پس اگر مشرکین مکہ کے سوا دوسرے مذاہب اسلام کے بتائے ہوئے خدا یا اسلامی طریقہ عبادت کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہو سکتے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع دوسرے مذاہب کے معبودوں یا ان کے طریق عبادت کو اختیار کرنے کے لئے تیار ہو سکتے تھے تو پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ گو الفاظ عام ہیں لیکن چونکہ بعض مذاہب ایسے ہیں جو اسلامی طریق عبادت کو اختیار کرسکتے ہیں اور چونکہ بعض مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے خدا کا مفہوم ایسے رنگ میں پیش کیا ہے کہ مسلمان ان کی عبادت کرسکتا ہے.اس لئے اس آیت میں ہم اَلْکٰفِرُوْنَ کے لفظ کے عام معنے نہیں لے سکتے بلکہ اسے صرف ایسے کافروں کے لئے مخصوص کرنا پڑے گا جو نہ ہماری عبادت کر سکتے ہیں نہ ہم ان کی عبادت کر سکتے ہیں.لیکن ایسا نہیں ہے اور سارے کے سارے غیر مسلم اس مضمون کے نیچے آتے ہیں جو اس سورۃ میں لکھا گیا ہے تو جب یہ بات ہے تو پھر اس سورۃ کے مفہوم کے لحاظ سے اَلْکٰفِرُوْنَ کے لفظ کو محدود اور مخصوص کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ عربی زبان قرآن کریم کے محاورہ اور اس سورۃ کے مضمون پر غور کرنے کے بعد اب ہم خارجی شہادتوں کو لیتے ہیں جن کی وجہ سے اس سورۃ میں مفسرین نے اَلْکٰفِرُوْنَ کو مخصوص اور محدودکرنے کی ضرورت سمجھی.ابن جریر، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے اَنَّ قُرَیْشًا دَعَتْ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِلٰی اَنْ یُّـعْــطُـوْہُ مَـالًا فَـیَـکُـوْنَ اَغْنٰی رَجُــلٍ بِـــمَـکَّــۃَوَ یُـزَوِّجُوْہُ مَا اَرَادَ مِنَ النِّسَآءِ
Page 227
فَقَالُوْا ھٰذَا لَکَ یَا مُـحَمَّدُ وَکُفَّ عَنْ شَتْمِ اٰلِھَتِنَا وَلَا تَذْکُرْ اٰلِھَتَنَا بِسُوْءٍ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَاِنَّا نَعْرِضُ عَلَیْکَ خَصْلَۃً وَّاحِدَۃً وَّلَکَ فِیْـھَا صَلَاحٌ قَالَ مَا ھِیَ قَالُوْا تَعْبُدُ اٰلِھَتَنَا سَنَۃً وَنَعْبُدُ اِلٰھَکَ سَنَۃً قَالَ حَتّٰی اَنْظُرَ مَا یَاْتِیْنِیْ مِنْ رَّبِّیْ فَجَآءَ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ الایۃ وَ اَنْزَلَ اللہُ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْۤ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَاِلٰی قَوْلِہٖ الشّٰكِرِيْنَ ( الدّر منثور سورۃ الکافرون) یعنی ابن عباس ؓ روایت کرتے ہیں کہ قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ کے سب آدمیوں سے زیادہ امیر بن جائیں گے اور آپ کی شادی جس عورت سے چاہیں وہ کرا دیں گے.پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم)یہ سب کچھ آپ کومل سکتا ہے آپ اس کے بدلہ میں صرف ہمارے معبودوں کو گالیاں دینی چھوڑ دیں اور آئندہ ان کا ذکر بری طرح نہ کیا کریں.لیکن اگر آپ ایسا نہ کریں تو ہم آخری بار آپ کے سامنے ایک بات رکھ دیتے ہیں وہ بات ایسی ہے کہ اس میں ہمارا اور آپ کا دونوں کا فائدہ ہے.آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے.آپ نے فرمایا میں اس وقت تک جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ میرے رب کی طرف سے اس کے متعلق ارشاد نہ آجائے.اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ وحی نازل ہوئی کہ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ آخر سورۃ تک.اسی طرح یہ کہقُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْۤ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ.وَ لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ١ۚ لَىِٕنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ.( الزّمر :۶۵تا۶۷) اسی طرح سعید بن منیاء مولیٰ ابی البختری سے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی مسند میں اور ابن الانباری نے مصاحف میں یہ روایت نقل کی ہے کہ لَقِیَ الْوَلِیْدُ بْنُ الْمُغِیْرَۃَ وَالْعَاصِیْ بْنُ وَائِلٍ وَالْاَسْوَدُبْنُ الْمُطَّلِبِ وَ اُمَیَّۃُبْنُ خَلْفٍ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا یَا مُـحَمَّدُ ھَلُمَّ فَلْنَعْبُدْ مَا تَعْبُدُ وَ تَعْبُدْ مَا نَعْبُدُ وَلْنَشْتَرِکْ نَـحْنُ وَ اَنْتَ فِیْ اَمْرِنَا کُلِّہٖ فَاِنْ کَانَ الَّذِیْ نَـحْنُ عَلَیْہِ اَصَـحُّ مِنَ الَّذِیْ اَنْتَ عَلَیْہِ کُنتَ قَدْ اَخَذْتَ مِنہُ حَظًّا فَاَنْزَلَ اللہُ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ حَتّٰی اِنْقَضَتِ السُّوْرَۃُ.یعنی ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمدؐ آئیے ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اورہم دین کے معاملہ میں سب کے سب شریک ہو جائیں اس سے فائدہ یہ
Page 228
ہو گا کہ اگر وہ چیز جس پر ہم ہیں آپ کی چیز سے زیادہ اچھی ہوئی تو آپ اس میں شریک ہو جائیں گے اور اس سے اپنا حصہ لے لیں گے اور اگر وہ چیز جس پر آپ ہیں ہماری چیز سے زیادہ اچھی ہوئی تو ہم اس میں شریک ہو جائیں گے اور اس سے اپنا حصہ لے لیں گے.اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی.(الدر المنثور السورۃ الکافرون) عبد الرزاق اور ابن منذر دونوں نے اپنی کتب میں وہب سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قریش نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اِنْ سَـرَّکَ اَنْ نَّتَّبِعَکَ عَامًا وَّ تَرْجِعَ اِلٰی دِیْنِنَا عَامًا فَاَنْزَلَ اللہُ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اِلٰی اٰخِرِ السُّوْرَۃِ.یعنی اگر آپ کو پسند ہو تو ہم ایک سال آپ کے پیچھے چلنے کے لئے تیار ہیں اور ایک سال آپ ہمارے پیچھے چلیں.اس پر اللہ تعالیٰ نے قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ والی سورۃ نازل فرمائی.(الدر المنثور السورۃ الکافرون) اسی طرح عبد بن حمید اور ابن المنذر نے ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے اِنَّ قُرَیْشًا قَالَتْ لَوِ اسْتَلَمْتَ اٰلِھَتَنَا لَعَبَدْنَا اِلٰھَکَ فَاَنْزَلَ اللہُ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ السُّوْرَۃَ کُلَّھَا.یعنی قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کرنے کے لئے تیار ہیں.اس پر اللہ تعالیٰ نے قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کی ساری سورۃ نازل کی.(الدر المنثور السورۃ الکافرون) ان روایتوں کی بنا پرمفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سورۃ میں يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ سے مراد خاص وہ کفار ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کے متعلق مذکورہ بالا سوال کیا تھا.جہاں تک اس امر کا سوال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار نے بعض دفعہ ایسی تجاویز پیش کی تھیں جن میں اپنے معبودوں سے نرمی کرنے کی خواہش کی گئی تھی اور اس کے بدلہ میں آپ کے اعزاز اور اکرام کرنے کے وعدے کئے گئے تھے.تو یہ امر نہ صرف احادیث سے ہی ثابت ہے بلکہ کثرت سے تاریخی روایتیں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں اور یہ واقعہ ایک تواتر کا رنگ رکھتا ہے لیکن جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ یہ سورۃ اسی غرض کے لئے اتاری گئی تھی یہ امر قابلِ غور بھی ہے اور مشکوک بھی ہے.ہم ان مذکورہ بالا روایتوں میں سے آخر کی تین روایتوں کو لے لیتے ہیں جو مختصر ہیں اور ان کا مضمون صرف یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے.یا سعید بن منیاء اور ابن عباس ؓ کی روایت کے مطابق سال کی شرط نہیں.انہوں نے صرف یہ کہا کہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے.بظاہر کفار کے منہ سے ایسی بات کا نکلنا عجیب نہیں معلوم ہوتا.جب ایک انسان خلافِ عقل بات کرتا ہے
Page 229
اوراُدھر یہ بھی دیکھتا ہے کہ میری بات بے اثر ہو رہی ہے اور لوگ میرے عقیدہ سے پھرے جا رہے ہیں تو اس قسم کی خلاف عقل باتیں کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ سورۃ ان مطالبات کے نتیجہ میں اتری اور کیا اس مطالبہ کے نتیجہ میں کسی سورۃ کے اترنے کی ضرورت تھی اور کیا اس مطالبہ کے نتیجہ میں ایک مستقل سورۃ کا اترنا کوئی معقول بات تھی؟ سو پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ صحاح ستّہ میں اس حدیث کا کہیں ذکر نہیں.اتنا اہم واقعہ کہ کفار نے ایک سوال کیا اور اس کے جواب میں ایک سورۃ اتری اس کا ذکر صحاح سِتہ میں نہ ہونا قابل تعجب معلوم ہوتا ہے.دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اس مطالبہ کے جواب میں کسی سورۃ کے اترنے کی عقلاً کوئی ضرورت تھی اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے.توحید کے متعلق پہلے دن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الہامات نازل ہوئے ہیں.مثلاً جو پہلی سورۃ اتری تھی اس میں گو توحید کا لفظ نہیں ہے لیکن ایک خدا کی عبادت کا ذکر ہے.چنانچہ فرماتا ہے اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ.خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ.اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ.الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ.عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق:۲تا۶) یعنی تُو اس خدا کا نام لے کر دنیا میں تبلیغ کر جس نے سب دنیا کو پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کی پیدائش میں اپنی محبت مخفی کر دی ہے.ہاں اسی کے نام کو دنیامیں پھیلا جو سب سے زیادہ معزز ہے جس نے انسان کو علوم تحریر سے سکھائے ہیں.یعنی ایک لمبے عرصہ تک قائم رہنے والی تعلیمات سے نوازا ہے اور ایسے علوم انسان کو سکھائے ہیں جن کو وہ پہلے نہ جانتا تھا.اس مضمون میں ایک تو ذات ِ باری کے کامل ہونے کی طرف اشارہ ہے.دوسرے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی الہام کے ذریعہ سے بنی نوع انسان کو ہدایت دیتا رہا ہے.تیسرےیہ بتایا ہے کہ الٰہی کلام میں ایسے علوم ہوتے ہیں کہ مخلوق کا کوئی فرد ان علوم تک خود بخود نہیں پہنچ سکتا.اب یہ سب باتیں شرک کی بیخ کنی کر دیتی ہیں.کیونکہ جب خدا تعالیٰ نبیوں کے ذریعہ سے تعلیم دیتا رہا ہے اور کامل تعلیم اس کی طرف سے آتی رہی ہے تو بتوں کے لئے اس نظامِ روحانی میں گنجائش ہی کہاں رہ جاتی ہے.پھر اس کے بعد قریب میں اترنے والی سورتیں سورۂ مزمل اور سورۂ مدثر ہیں.سورۂ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا (المزّمل:۱۰) خدا مشرق کا بھی خدا ہے اور مغرب کا بھی خدا ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں.بس اسی پر اپنا سارا توکل کر.پھر سورہ ٔ مدثر میں فرماتا ہے وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ(المدّثر:۴) صرف اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر.وَالرُّجْزَ فَاھْجُرْ(المدّثر:۶) اورشرک کو بالکل دور کردے.پس ایسے واضح بیان کے بعد کہ شرک کو ترک کر و صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور مشرق و مغرب کا صرف ایک خدا ہے کوئی دوسرا خدا نہیں اس کے اوپر توکل کرو.کفار کے
Page 230
اس مزعومہ سوال کے جواب کے لئے کسی اور سورۃ کے نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار سال سے ایک خدا کی عبادت کرتے چلے آرہے تھے.آپ کا عمل بھی یہی تھا کہ ایک خدا کے سوا دوسرا کوئی نہیں اور سارے مکہ والوں سے لڑائی ہی اس بات پر تھی کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں.ان تمام باتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ لوگوں نے آپ سے آکر یہ سوال کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے رہبری طلب کی.تب خدا تعالیٰ نے یہ سورۃ اتار کر بتایا کہ ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کرنی کتنی فضول اور خلاف عقل بات ہے.کیاکوئی شخص اس کہانی کو مان سکتا ہے کہ ایک ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان سے کسی نے کہا کہ آؤ کچھ دن تم ہمارے عیسیٰ کو خدا مان لیاکرو کچھ دن ہم تمہارے خدا کو خدامان لیا کریں گے تو اس مسلمان نے کہا کہ اچھا میں اپنے علماء سے پوچھ کر اس کا جواب دوںگا؟ اگر ایک جاہل سے جاہل مسلمان بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تو عقل مندوں کے سردار اور توحید کے علمبردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خیال کرلینا کہ آپ اس سوال کو سن کر (میں اس سوال کو عجیب نہیں سمجھتا.ایک شکست خوردہ قوم اپنی گھبراہٹ میں کئی بے وقوفی کی باتیں کر لیتی ہے میں صرف اس بات کو خلاف عقل قرار دے رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو سن کر کسی قسم کے تردد کا اظہار کیا اور خدا تعالیٰ کے جواب کا انتظار کیا)اس کے جواب کے لئے خدا تعالیٰ کی راہنمائی کے منتظر رہے یا یہ کہ آپ کے دعویٰ کے چار سال بعد بھی آپ کو ایسی راہنمائی کی ضرورت تھی.کم سے کم میرے نزدیک تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کو کوئی معقول انسان ایک منٹ کے لئے بھی تسلیم نہیں کر سکتا.یہ سوال نہ صرف ایسا تھا جس کا جواب پہلے سے قرآن کریم میں آچکا تھا بلکہ اس میں اور بھی بہت سے نقائص تھے جن کا جواب دینے کے لئے کسی وحی کی ہدایت کی ضرور ت نہیں تھی.مثلاًسوال یہ تھا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگ جائیں.کیا اس سوال میں کوئی اہمیت تھی جس کے جواب کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کی ضرورت ہوتی.اس سوال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تویہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ جن معبودوں کو نہیں مانتے ان کی عبادت کریں اور اپنی طرف سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں اور جس کی ہم عبادت بھی کرتے ہیں اس کی ہم عبادت کرنے لگ جائیں گے.یہ پیشکش تو ایسی ہی ہے جیسے ہمارے ملک میں مشہور ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے گھر گئی جس کے پاس چکّی تھی اور اس سے درخواست کی کہ کچھ دیر کے لئے وہ اسے چکّی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنے دانے پیس لے.جب وہ دانے پیسنے لگی تو گھر والی عورت کو بھی خیال
Page 231
آگیا کہ میں بھی تھوڑی دیر چکّی پیسوں.اس پر دانے پسوانے کے لئے جو عورت آئی تھی اس سے گھر والی نے کہا کہ اٹھو میں تمہاری جگہ دانے پیستی ہوں.جب چکی والی دانے پیسنے میں مشغول ہوئی تو جو دانے پیسنے کے لئے لائی تھی اس نے گھر والی کے کھانے پر سے کپڑا اٹھایا اور یہ کہہ کر اسے کھانا شروع کر دیا کہ بہن مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ تم میراکام کرو اور میں تمہارا کوئی کام نہ کروں.اس لئے تم میرے دانے پیسو میں تمہارا کھانا کھاتی ہوں.یہ لطیفہ لوگوں نے بعض فاتر العقل لوگوں کی سادگی یا بے وقوفی ظاہر کرنے کے لئے بنایا ہوا ہے.مگر کیا کوئی شخص اس لطیفہ کو سن کر اس حیرت میں پڑ سکتا ہے کہ جو بات اس بے وقوف عورت نے کہی تھی اس کو کس طرح حل کیا جائے.اس کا کیا جواب دیا جائے؟ کفار کا سوال بھی اس عورت کے اس فقرہ سے کم بے ہودہ نہیں تھا.شاید ہمارے مفسرین نے یہ خیال کر لیا ہے کہ مکہ کے مشرک صرف اپنے بتوں کو مانتے تھے خدا کو نہیں مانتے تھے اس لئے ان کا یہ مطالبہ کہ تم ہمارے معبودوں کو ماننے لگ جاؤ ہم تمہارے معبود کو ماننے لگ جائیں گے.خواہ خلاف ِ ایمان اور خلاف ِ دین تو ہو لیکن خلاف عقل نہیں تھا.حالانکہ یہ مطالبہ خلاف دین اور خلاف ِ ایمان ہی نہیں خلاف ِ عقل بھی تھا کفار مکہ خدا تعالیٰ کو اسی طرح مانتے تھے جس طرح مسلمان مانتے تھے اور اس کو سب بتوں کا سردار اور آقا سمجھتے تھے.غلطی صرف یہ تھی کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے کچھ اور چھوٹے معبودوں کی بھی ضرورت سمجھتے تھے.قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ١ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ( الزّمر:۴) یعنی وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بناتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی صرف اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں.اس آیت سے صاف پتہ لگتا ہے کہ مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ خدا ہی تمام دنیا کا بادشاہ ہے اور صرف یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خدا کے سوا جو اور معبود ہیں وہ خدا کے پیارے ہیں اور ہم ان کی اس لئے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کا مقرب بنا دیں اور ہمارے سفارشی بن جائیں.پس جبکہ مشرکین خدا تعالیٰ کو مانتے تھے.خدا تعالیٰ کے قرب کو ضروری سمجھتے تھے اور معبودانِ باطلہ کی محض اس لئے عبادت کرتے تھے کہ وہ ان کی خدا تعالیٰ کے پاس سفارش کر دیں تو ان حالات میں یہ کیوں کر سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے اور اگر وہ خدا کی عبادت کرتے تھے تو پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، کتنا احمقانہ سوال بن جاتا ہے.خدا تعالیٰ پر ایمان تو مشرکوں اور مسلمانوں میں مشترک تھا ما بہ النزاع صرف معبودانِ باطلہ کی ذات تھی.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرنا کہ تم اس چیز کو مان لو جس پر جھگڑا ہے تو ہم اس چیز کومان لیں گے جس کو ہم بھی مانتے ہیں ایک ایسی بات تھی
Page 232
جس کو شاید ایک نیم عقل آدمی بھی سن کر ہنس پڑے اور پوچھے کہ میاں تم دیتے کیا ہو اور مانگتے کیاہو؟ دیتے تو تم وہ چیز ہو جو پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور مانگتے وہ ہو جس پر نہ تمہارا حق ہے نہ کسی اور کا حق ہے تو یہ صلح کیا ہوئی اور یہ فیصلہ کیا ہوا؟ غرض کفار کا مطالبہ جو ان حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے وہ ایسا خلاف عقل ہے اور ایسے امور کے متعلق ہے جن کا فیصلہ قرآن شریف میں پہلے سے ہو چکا تھا جس کی موجودگی میں کسی سورۃ کے اترنے کی ضرورت نہیں تھی.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الگ رہے آپ کے غلام بھی اس سوال کا جواب بڑی عمدگی سے دے سکتے تھے.پس کفار نے مذکورہ بالا سوال کرنے کی ضرور حماقت کی ہو گی مگر اس حماقت کے جواب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہ کہا ہو گا کہ یہ ایک اہم سوال ہے میں خود اس کا جواب نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر جواب دوں گا.اور نہ خدا تعالیٰ نے یہ خلاف عقل بات کی ہو گی کہ اس کے جواب میں ایک سورۃ نازل کر دی جس میں صرف وہ مضمون تھاجو چار سال سے مسلمانوں کی طرف سے پیش ہو رہا تھا اور جس کی تائید میں مسلمان مرد بھی اور مسلمان عورتیں بھی اور مسلمان آزاد بھی اور مسلمان غلام بھی یکے بعد دیگرے اپنی جانیں قربان کر رہے تھے.میرا اوپر کے مضمون سے یہ مطلب نہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی رنگ میں کیا کرتے تھے جس میں کہ محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے.اس رنگ میں تو نام نہاد مؤحد قومیں بھی عبادت نہیں کرتی تھیں.مثلاً یہودی بھی اس رنگ میں عبادت نہیں کرتے تھے.عیسائیوں میں سے مؤحد بھی اس رنگ میں عبادت نہیں کرتے تھے.اسلامی طریق عبادت تو ایک نو ایجاد طریقہ ہے.پہلے اس طریق کی عبادت دنیا میں کہیں نہیں تھی.کیونکہ توحید ِ کامل کا نظریہ ہی اسلامی نظریہ ہے.اس سے پہلے دنیا میں توحیدِ کامل پائی ہی نہیں جاتی تھی.پس یہ ٹھیک ہے کہ مکہ کے لوگ خدا تعالیٰ کی اس شکل میں عبادت نہیں کرتے تھے جس شکل میں مسلمان کرتے تھے مگر وہ خدا تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتے تھے.مثلاً ان کے ہاں عبادت کا ایک ذریعہ نذر ماننا تھا.قرآن کریم سے صاف ثابت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نذر مانا کرتے تھے چنانچہ سورۂ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَ هٰذَا لِشُرَكَآىِٕنَا۠١ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآىِٕهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ١ۚ وَ مَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآىِٕهِمْ١ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ(الانعام:۱۳۷) یعنی کفار مکہ اپنی کھیتی اور اپنے جانوروں کے گلوں میں سے ایک حصہ اللہ کی نذر میں دے دیا کرتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے اور کچھ حصہ معبودانِ باطل
Page 233
کے نام پر وقف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ان کا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو ان کے معبودانِ باطل کا ہے وہ خدا تعالیٰ کے نام پر نہیں دیا جا سکتا.لیکن جو اللہ کے نام کا ہے وہ ان کے معبودانِ باطل کے نام پر دیا جا سکتا ہے.یہ کیسا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں (ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بڑی ہے اور معبود اس کے تابع ہیں جس طرح باپ کا مال بیٹوں کو جا سکتا ہے اسی طرح خدا کا مال معبودانِ باطل کو جا سکتا ہے لیکن معبودانِ باطل کے حصہ کا مال خدا کے نام پر نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ چھوٹے ہیں اور چھوٹے کا مال بڑے کی طرف نہیں جاتا)اب اس آیت سے دیکھو خدا تعالیٰ کی عبادت بالکل ثابت ہے.رکوع سجود تو وہ بتوں کے لئے بھی نہیں کرتے تھے.بتوں کی عبادت کا طریق بھی ان میں یہی تھا کہ ان کی تعریف میں شعر کہتے اور ان کے نام پر نذریں دیتے.ہاں چونکہ بت نظر آتے تھے کبھی کبھار ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے دعا بھی کر لیا کرتے تھے.پس مکہ کے لوگ بت پرست تو ضرور تھے مگر اللہ کی عبادت کے تارک نہیں تھے.اپنی عقل اور روایتوں کے مطابق وہ اپنے بتوں کی بھی پوجا کرلیاکرتے تھے اور اپنی عقل اور روایتوں کے مطابق وہ خدا کی بھی پوجا کر لیا کرتے تھے.تاریخ سے بھی اس کے متعلق بہت سے واقعات مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عملاً مکہ کے لوگ خدا تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے.چنانچہ حضرت عبد المطلب کا ایک مشہور واقعہ ہے جس کی تفصیل تاریخ ابن ہشام میں یوں لکھی ہے.حضرت ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عبد المطلب نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں ایک دفعہ سو رہا تھا کہ ایک شخص مجھے نظر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ طیبہ کا کنواں کھودو.میں نے کہا کہ طیبہ کیا شے ہے تو میں جاگ پڑا.اسی طرح کئی راتیں خواب آتی رہی اور ہر دفعہ فرشتہ کنویں کا دوسرا نام لیتا تھا (تاریخ میں تفصیل موجود ہے.اختصار کے خیال سے چھوڑا جاتا ہے) آخری روز اس نے زمزم کا نا م لیا اور اس جگہ کی علامتیں بتائیں جہاں وہ کنواں موجود ہے.اس خواب کی بنا پر حضرت عبد المطلب نے کدال لیا اور اپنے بیٹے الحرث کو ساتھ لیا (اس وقت تک ان کے یہی ایک بیٹے تھے )اور کنواں کھودنا شروع کیا.تھوڑی دیر کے بعد کنوئیں کا گھیر نظر آگیا.زمزم کا کنواں حضرت اسمٰعیل کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا تھا حضرت ہاجرہ ؓ نے اس کی منڈیر بنا دی تھی اور بعد میں عربوں نے اسے کنوئیں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا.مگر یہ کنواں بعد میں بند ہو گیا یعنی مٹی نے اسے بھر دیا تھا.حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں پھر دکھایا.جب کنوئیں کا گھیر نظر آگیا تو حضرت عبد المطلب نے شکریہ سے نعرہ تکبیر بلند کیا (یہ ثبوت ہے کہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اور اس کا نام بھی بلند کرتے تھے)جب قریش نے ان کا نعرہ سنا تو سمجھ گئے
Page 234
کہ خواب کی ہدایت کے مطابق کنواں مل گیا ہے اور دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اس کنوئیں میں ہمارا بھی حصہ تسلیم کریں.حضرت عبد المطلب نے انکار کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے یہ کنواں خاص طور پر مجھے دیا ہے میں تم کو کس طرح شریک کر لوں.اس پر قریش نے جھگڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہم اپنا حق لئے بغیر نہ رہیں گے.اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اچھا کوئی ثالث مقرر کر لو.انہوں نے کہا کہ بنو سعد بن ہذیم کی کاہنہ کو ثالث مقرر کرتے ہیں.آپ نے منظور کیا اور ایک جماعت قریش کی ساتھ لے کر چلے راستہ میں پانی ختم ہو گیا.بہت کوشش کی نہ ملا.کنوئیں کھودے تو پھر بھی پانی نہ نکلا.حضرت عبد المطلب نے کہا اس طرح بے کار بیٹھنے سے فائدہ نہیں چلو اِدھر اُدھر پھر کر پانی تلاش کریں.جب سب قوم سوار ہو گئی حضرت عبد المطلب بھی سوار ہو گئے.چلتے ہوئے ایک جگہ آپ کی اونٹنی کے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی نکل آیا.آپ نے قریش کو آواز دی اور کہا ’’قَدْ سَقَانَا اللہُ‘‘.اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لئے پانی دیا ہے (اس سے بھی ظاہر ہے کہ وہ اصل معبود اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھتے تھے)اس پر انہوں نے کہا کہ ’’اللہ کی قسم‘‘(دیکھو کفار مکہ بھی اللہ کی قسم کھاتے تھے ) ہمارے خلاف تجھے ڈگری مل گئی ہے.’’اللہ کی قسم‘‘ہم تجھ سے اب زمزم کے بارہ میں نہیں جھگڑیں گے.جس خدا نے تجھے یہاں پانی دیا ہے اسی نے تجھے زمزم دیا ہے.اس کے بعد سب مکہ لوٹ آئے، جب مکہ پہنچے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ قریش نے یہ جھگڑا اس لئے کیا تھا کہ میرا ساتھی کوئی نہ تھا.اگر مجھے دس لڑکے ملیں اور وہ سب جوان ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ میرے ساتھ مل کر میرے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں تو لَیَنْحَرَنَّ اَحَدَھُمْ لِلہِ عِنْدَ الْکَعْبَۃِ، تو خدا کی قسم عبد المطلب ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس شکریہ میں کعبہ کے پاس قربان کر دے گا.جب خدا تعالیٰ نے ان کو دس بیٹے دے دیئے تو وہ کعبہ میں آئے.سرداران قریش کو جمع کیا اور خواہش کی کہ ان کی نذر پورا کرنے میں ان کی مدد کریں.انہوں نے کہا کس طرح.تو آپ نے جواب دیا کہ ہُبل بت کے پیالوں کے ذریعہ سے (یہ ہبل بت کعبہ کے پہلو میں تھا اور اس کے پاس سات پیالے رکھے تھے جن کے ذریعہ سے قرعہ ڈالا جاتا تھا)چنانچہ قرعہ ڈالا گیا اس وقت عبد المطلب ہُبل کے پاس کھڑے ہو کر ’’اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے‘‘(غور کرو ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کا رواج تھا)جب قرعہ نکلا تو وہ عبد اللہ کے نام کا تھا.مکہ والوں نے کہا ہم اسے ذبح نہیں کرنے دیں گے.چنانچہ بڑے جھگڑے کے بعد مدینہ کی ایک کاہنہ کے پاس فیصلہ کے لئے لے گئے.اس نے فدیہ کی تجویز کی اور کہا کہ کعبہ میں دس اونٹ ذبح کر دو مگر عبد المطلب کو بغیر قرعہ ڈالنے کے یہ گوارا نہ تھا اس لئے انہوں نے عبد اللہ اور دس اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا.اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کی مگر قرعہ پھر عبد اللہ کے نام کا نکلا.پھر اور دس اونٹ بڑھائے گئے پھر قرعہ
Page 235
عبد اللہ کے نام کا نکلا.آخر بڑھاتے بڑھاتے سو اونٹ پر جا کر قرعہ اونٹوں کے نام کا نکلا.سبحان اللہ.حضرت عبد اللہ محمد رسول اللہ ؐ کے والد بننے والے تھے.فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے ؎ نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز بہرحال اس فیصلہ پر مکہ والوں نے کہا لو اب’’تمہارا رب‘‘راضی ہو گیا ہے.چنانچہ سو اونٹ ذبح کر دیئے گئے.(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام ذکر حفر زمزم و جرٰی من الخلف فیھا) یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مکہ والے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے.اس کی نذریں مانتے تھے.اس سے دعائیں کرتے تھے اور بتوں کو صرف اس کے تابع معبود سمجھتے تھے پس مکہ والوں کی نسبت یہ نہیں کہا جا سکتاکہ وہ بتوں کے پجاری تھے خدا تعالیٰ کے نہیں.پس ان کا یہ کہنا کہ تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کروہم اللہ کی پوجا کر لیا کریں گے ایک احمقانہ مطالبہ تھا کیونکہ محمد رسول اللہ ؐ ان کے بتوں کو نہیں مانتے تھے مگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو مانتے تھے.پس ایسے احمقانہ مطالبہ پر کسی سورۃ کے نزول کی خواہش خلاف عقل تھی.ہر مسلمان بچہ بھی اس کا جواب دے سکتا تھا.تیسراسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سوا ل کے جواب میں ایک مکمل سورۃ اتر سکتی تھی؟ اس سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ ہر گز نہیں.کیونکہ اگر ہم اس سورۃ کو ان سوالوں کے جواب میں نازل شدہ مانیں تو اس سورۃ کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہتی.تب اس سورۃ کا صرف اتنا مضمون بن جاتا ہے کہ اے کافرو!میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا تم میرے معبود کی عبادت نہیں کرتے.تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ.قرآن جیسی اہم کتاب کی ایک سورۃ کو صرف اتنے سے مضمون کے لئے محدود کر دینا جو تمام معارف اور باریکیوں اور روحانی امور سے خالی ہو بہت ہی تنگ نظری کا ثبوت ہوگا.قرآن کریم کی تو کوئی سورۃ بھی ایسی نہیں جو کہ لطیف اور وسیع معارف سے خالی ہو اور یہ مضمون جو ان روایتوں کی وجہ سے اس سورۃ کا بن جاتا ہے اوّل تو پامال مضمون ہے دوسرے نہایت محدود مضمون ہے اور اگر اس کو مختصر طور پر بیان کریں تو یہی بنتا ہے کہ جاؤ تم نے میر ی نہیں سنی میں تمہاری نہیں سنوں گا.قرآن شریف کی تو کوئی آیت یا سورۃ ایسی نظر نہیں آتی جس میں اس قسم کا مضمون ہو.وہاں تو ایک ایک لفظ کے نیچے سے معارف کے دریا بہتے چلے جاتے ہیں.پس یہ روایتیں جس طرح اس سورۃ کے مضمون کو تنگ اور محدود کر دیتی ہیں اس کو دیکھ کر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان روایتوں کے اند رمذکور سوالوں کے جواب میں کوئی سورۃ نازل نہیں ہو سکتی تھی.بلکہ اگر اس سورۃ کو ان سوالوں کے جواب میں سمجھا جائے تو اس سورۃ کے وسیع مطالب بالکل چھپ جاتے ہیں
Page 236
اور اسی وجہ سے میں اس خیال کی تردید اس تفصیل سے کر رہاہوں ورنہ کوئی ضرورت نہ تھی کہ میں اس کے پیچھے پڑتا.اب میں سب سے پہلی روایت کو لیتا ہوں جسے میں چھوڑ کر آیا تھا اور جو حضرت ابن عباس ؓ سے ابن جریر نے نقل کی ہے.اس میں دو باتیں جمع ہیں.اوّل یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ جو آپ کو مکہ میں سب سے زیادہ امیر بنا دے گا اور جس عورت کو آپ پسند کریں اس سے ہم آپ کی شادی کر دیں گے اس کے بدلہ میں آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے باز آجائیں اور اگر آپ ہماری اس بات کو نہ مانیں تو پھر ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے اور دوسرے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں.(جامع البیان سورۃ الکافـرون) اس روایت کا پہلا حصہ تاریخی طور پر بہت سی روایتوں سے ثابت ہے لیکن اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس پیغام کے سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں کھڑا کر دیں تب بھی میں خدائے واحد کی پرستش کو نہ چھوڑوں گا( السیرۃ النبویۃ لابن ھشام مباداۃ رسول اللہ قومہ وماکان منھم) اس جواب کے ہوتے ہوئے زیر بحث حدیث میں یہ فقرہ کتنا بھونڈا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ’’میں اپنے رب کے جواب کے بعد جواب دوںگا.‘‘تمام دوسری احادیث اور تاریخ اس امر پر متفق ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسے ماننے کو تیار نہیں کفار جو چاہیں کر لیں میں خدائے واحد کی عبادت کو ترک نہیں کر سکتا.جس شخص نے یہ جواب دیا ہو کیا وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ٹھہر جاؤ میں اصل جواب خدا تعالیٰ کی ہدایت کے بعد دوں گا.پس دوسری احادیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ حصہ اس حدیث کا بالکل غلط اور خلاف عقل ثابت ہوتا ہے.خود اس حدیث کے مضمون میں بھی اختلاف ہے.بعض محدثین نے اسی مضمون کی حدیث نقل کی ہے لیکن اس حصہ کو تر ک کر دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جواب آنے پر میں جواب دوں گا چنانچہ علامہ زمخشری نے اس حدیث کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے.’’بعض قریش نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاکہ اے محمد(صلعم)آئیں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے.آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے.اس پر آپ نے فرمایا میں کسی کو خدا تعالیٰ کا شریک قرار دینے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں الخ.‘‘اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ اچھا ٹھہرو میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ت ایمانی کے
Page 237
عین مطابق فوراً جواب دیا کہ خدا کی پناہ.میں ایسا گناہ کس طرح کر سکتا ہوں.یہ حدیث کشاف ہی کے مطابق علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اور مولانا شیخ اسمٰعیل بروسوی نے اپنی تفسیر روح البیان میں لکھی ہے.علامہ ابن حیان نے اپنی تفسیر بحرِ محیط میں گو حدیث کے الفاظ میں معاذ اللہ کے الفاظ تو نہیں لکھے مگر یہ حصہ کہ ٹھہرو خدا کا حکم آجائے جو اصل میں قابل اعتراض الفاظ ہیں درج نہیں کئے.گویا ان الفاظ کو حذف کر کے ان کے غلط ہونے کی تصدیق کر دی ہے.امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس ٹکڑے کا کہیں ذکر نہیں کیا.جہاں تک احادیث کا تعلق ہے امام مذکور سب ان محدثین پر فوقیت رکھتے ہیں کہ جو تفسیر کے متعلق احادیث جمع کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ ثقہ روایات لانے کی کوشش کرتے ہیں.علامہ قرطبی نے بھی جو بڑ ے فقیہ ہیں اس ٹکڑے کا ذکر نہیں کیا.بڑے مفسرین میں سے (جو درایت سے بھی کام لیتے ہیں اور صرف احادیث خواہ وہ کسی طبقہ کی ہوں جمع کرنے کی کوشش نہیںکرتے)صاحب تفسیر رازی ایسے ہیں جنہوں نے اس مضمون کو نقل ہی نہیں کیا بلکہ اس پر نمک مرچ بھی لگایا ہے.وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قوم تیرے پاس آئی اور تجھے لالچ دی کہ وہ تیری اتباع کریں گے اور تُو ان کے دین میں ان کی اتباع کر اس پر تو نے انکار نہ کیا اور ان کی بات کو ردّ نہ کیا حالانکہ میں نے تجھ سے اس اس طرح نیک سلوک کیا تھا.نَعُوْذُ بِاللہِ مِنْ ھٰذِہِ الْـخُرَافَاتِ.بہرحال رازی کے سواباقی جید مفسرین نے جو نقل کے ساتھ عقل سے بھی کام لینا جائز سمجھتے ہیں یا تو ان روایات کے خلاف روایات نقل کی ہیں (گو افسوس انہوں نے رواۃ حدیث درج نہیں کئے )یا روایت کے قابل اعتراض حصہ کو ترک کر کے اپنی رائے ظاہر کر دی ہے کہ وہ اسے معیوب اور غلط سمجھتے ہیں پس ان سب امور پر غور کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان احادیث کے قابل اعتراض حصہ کے خلاف دوسری روایات بھی موجود ہیں اور تاریخ بھی تواتر سے ان کے قابلِ اعتراض حصہ کو ردّ کرتی ہے.گو اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ کفار نے اپنی حماقت سے یہ پیشکش تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی کہ آپ ان کے معبودوں کے معاملہ میں نرمی سے کام لیں تو وہ آپ کو اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں مگر آپ نے اسی وقت اس امر کو سختی سے ردّ کر دیا تھا اور جب بات یوں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سورۃ اس سوال کے جواب میں نہیں اتری بلکہ اس کا مضمون اس سوال سے الگ اور بالا ہے گو الفاظ ایسے ہیں کہ ایک ناواقف آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے کہ شاید اس سوال کے ساتھ اس مضمون کا تعلق ہو.(باء)بعض لوگوں نے یہ شبہ پیدا کیا ہے کہ اس سورۃ سے پہلے قُلْ آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ
Page 238
کسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے لیکن اگر یہ درست ہے تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کس سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں.یہی مفسر ان سورتوں کے بارہ میں خاموش ہیں اور کسی انسان کے سوال کے جواب کی وہاں ضرورت محسوس نہیں کرتے.اصل بات یہ ہے کہ قُلْ کا لفظ اعلان کے لئے آیا ہے یعنی اس سورۃ کے مضمون کا خوب اعلان کر.یوں تو سب سورتوں کا مضمون اعلان کے قابل ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ (المآئدۃ:۶۷) اے رسول جو کلام قرآنی تجھ پر نازل ہوتا ہے وہ سب کا سب لوگوں تک پہنچا دے.پس قرآن کا کوئی حصہ چھپانے والا نہیں لیکن بعض مضمون وقت کے لحاظ سے خوب پھیلانے والا ہوتا ہے اس لئے اس کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی جاتی ہے.چنانچہ پانچ سورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کے شروع میں قُلْ کے لفظ آتے ہیں جس کے یہ معنے ہیں کہ ان کے مضمون کا خوب اچھی طرح اعلان کر دو.یہ سورتیں سورۂ جن، سورۂ کافرون، سور ۂ اخلاص، سورۂ فلق اور سورہ ٔ الناس ہیں.ان سورتوں کے علاوہ کم و بیش تین سو چھ آیتوں سے پہلے بھی یہ لفظ آتا ہے اورجہاں بھی آتا ہے ما بعد کے مضمون کی اہمیت بتانے کے لئے آتا ہے.مجموعی نظر ان آیات اور سورتوں پر ڈالی جائے تو ایک لطیف مضمون نکل آئے مگر تفسیر ایسے مضامین بیان کرنے کا مقام نہیں.یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ قُلْ کا لفظ بعد کے مضمون کی اہمیت بتانے اور اس کے اعلان کرنے کا حکم دینے کے لئے استعمال کیا گیا ہے کسی سوال کے جواب پر اشارہ کرنے کے لئے نہیں.قرآن کریم کی آخری تین سورتوں سے پہلے اس لفظ کا استعمال بھی یہی بتاتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم ختم ہو رہا تھا اس کا خلاصہ آخر میں پیش کر دیا گیا اور ان سورتوں کے مضمون کی اشاعت کی طرف خاص توجہ دلا دی تاکہ خلاصہ کے ذریعہ سے سارےمضمون سے اجمالاً لوگ واقف ہو جائیں.ایک سوال اس جگہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا تو اس وقت تو قُلْ کا لفظ اچھا لگتا تھا.جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی تلاوت کی یا دوسروں کو سنائی تو پھر قُلْ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وحی کے وقت قُلْ کہہ کے وحی شروع کی جاتی.مگر قُلْ کے لفظوں کو قرآنی وحی میں شامل نہ کیا جاتا.اب تو یہ لطیفہ بن گیا ہے کہ مثلاً سورۂ کافرون کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ پہلے کہتا ہے ’’کہہ‘‘.یہ ’’کہہ‘‘ کا لفظ کہنے والا کون ہوتا ہے اور کسے کہتا ہے.اگر تلاوت کے وقت اس لفظ کو اڑا دیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا.اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ’’قُلْ ‘‘کا لفظ ان مضامین یا سورتوں سے پہلے آتا ہے جن
Page 239
کے اعلان عام کا ارشاد ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کسی امر کا اعلان عام ایک آدمی نہیں کر سکتا.ایسے اعلان کا ذریعہ ایک جماعت ہی ہو سکتی ہے.جو نسلاً بعد نسلٍ یہ کام کرتی چلی جائے تاکہ ہر قوم و ملک کو بھی وہ پیغام پہنچ جائے.اور ہرنسل اور ہر زمانہ کے لوگوں کو بھی وہ پیغام پہنچ جائے اگر وحیٔ متلو میں یعنی قرآن کریم میں قُلْ کا لفظ نہ رکھا جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حکم چلتا.آپ کے بعد یہ حکم نہ چلتا.لیکن جبکہ قرآن کی وحی میں یہ لفظ شامل کر دیا گیا تو اب اس کے متواتر تا قیامت جاری رہنے کی صورت پیدا ہو گئی.جب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ تو کافروں کو مخاطب کر کے کہہ دے کہ اے کافرو! میں تمہارے معبود کی عبادت قطعاً نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا.تو آپ نے یہ اعلان کافروں میں کر دیا مگر قُلْ کا لفظ پہلے نہ ہوتا تو مسلمان سمجھتے یہ محمد رسول اللہ ؐکا کام تھا ختم ہو گیا.لیکن جب آپ نے اپنی وحی مسلمانوں کو سنائی اور یوں پڑھا قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ تو ہرمسلمان نے سمجھ لیا کہ یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے نہ تھا بلکہ میرے لئے بھی تھا کیونکہ میرے سامنے جب وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے تو اس کے پہلے قُلْ کہا ہے جس کا مخاطب میں ہی ہو سکتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں.کیونکہ وہ تو پڑھ رہے ہیں سن تو میں رہا ہوں.پس اس نے اس حکم کی تعمیل میں یہ پیغام آگے پہنچا دیا.لیکن چونکہ قُلْ کا لفظ وحی میںتھا اس نے بھی اگلے شخص کے سامنے اسی طرح پیغام پہنچا دیا کہ قُلْ کا لفظ بھی دہرایا اور اس تیسرے شخص کے سامنے جب قُلْ کا لفظ کہا گیا تو اس نے سمجھ لیا کہ صرف مجھے پیغام نہیں پہنچایا گیا بلکہ مجھ سے یہ بھی خواہش کی گئی ہے کہ میں آگے دوسروں تک یہ پیغام پہنچا دوں.پھر اس تیسرے آدمی نے چوتھے کو جب پیغام دیا تو پھر قُلْ کہا کیونکہ یہ وحی کا حصہ ہے اسے چھوڑا نہیں جا سکتا.اس لفظ کے سننے سے پانچویں نے بھی سمجھ لیا کہ میں نے ہی اس حکم پر عمل نہیں کرنا بلکہ آگے دوسروں تک بھی یہ حکم پہنچانا ہے.غرض اس طرح تاقیامت اس حکم کے دہرانے کا انتظام کر دیا گیا.پس دیکھو کہ قُلْ کے لفظ کو وحی کا حصہ بنا کر کتنا بڑا کام کیا گیا ہے.جب عام قرآنی سورتوں کو انسان پڑھتا ہے تو اسے وہ حکم پہنچ جاتا ہے جو ان میں ہے.مگر جب وہ اس سورۃ یا آیت کو پڑھتا ہے جس سے پہلے قُلْ لکھا ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے آگے پہنچاتے چلے جانا میرا فرض ہے اور وہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل کی نصیحت کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ تم یہ پیغام اپنے بعد کے لوگوں تک اور وہ اپنے بعد کے لوگوں تک پہنچا دیں.اب اس حکمت کو دیکھ کر سمجھ لو کہ وہ لوگ کتنے دھوکے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ قُلْ کا لفظ وحی میں کیوں رکھا گیا ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہنی تھی ان سے کہہ دی پھر قُلْ کا کیا فائدہ.اگر یہ لفظ وحیٔ متلو میں شامل نہ کر دیا جاتا تو اعلان عام کی غرض فوت ہو جاتی اور غیر متناہی تبلیغ کا راستہ کبھی نہ کھلتا.
Page 240
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کی جو لفظ قُلْ کو وحی میں شامل کرنے سے پیدا کی گئی ہے ایک خاص پیرایہ میں نقل کی ہے اپنے آخری حج میں جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے آپ نے منیٰ میں صحابہ ؓ میں ایک وعظ فرمایا اور اس کے آخر میں فرمایا اَلَا لِیُبَلِّــغِ الشَّاھِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ یُبَلِّغُہُ یَکُوْنُ اَوْعٰی لَہُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَـمِعَہُ ثُمَّ قَالَ اَلَا ھَلْ بَلَّغْتُ.(مسلم کتاب القسامۃ والمحاربین باب تغلیظ تحریم الدماء والاعراض) یعنی آخر میں فرمایا کہ جوحاضر ہیں وہ غیر حاضروں تک میری بات پہنچا دیں کیونکہ ممکن ہے کہ جو غیر حاضر ہے وہ حاضر سے اس معاملہ کی اہمیت سمجھنے پر زیادہ قادر ہو.پھر فرمایا سنو کیا میں نے تم کو یہ حکم الٰہی پہنچا دیا ہے اس وعظ میں بھی آپ نے قُلْ کا اختیار کردہ طریق استعمال کیا ہے کہ ہر حاضر غیر حاضر تک بات پہنچاتا جائے کیونکہ بعض دفعہ بعد میں آنے والے پہلوں سے زیادہ حکم کی اہمیت سمجھنے والے اور اسے جاری کرنے والے ہوتے ہیں.آج کل لوگ بے نام کارڈ ڈال کر بھجوا دیتے ہیں اور ان میں لکھ دیتے ہیں کہ اس خط کا مضمون نقل کر کے دس اور آدمیوں کو بھجوا دو.کچھ لوگ اس پر عمل کر کے دس اور کو وہ مضمون لکھ کر بھجوا دیتے ہیں اور سارے ملک میں وہ بات پھیل جاتی ہے.آج کل بہت سی لغو باتوں کے متعلق یہ طریق اختیار کیا جاتا ہے مگر اشاعت کے لئے یہ طریقہ عمدہ ہے بعض قرآنی سورتوں یا آیتوں سے پہلے قُلْ کا لفظ رکھ کر قرآن نے بھی یہی طریق اختیار کیا ہے اور گویا اس طریق کی ایجاد کا سہرا بھی قرآن کے سر پر ہے.اب میں حدیث کے دوسرے حصہ کو لیتا ہوں جو یہ ہے کہ کفار نے پہلی تجویز کے بعد دوسری تجویز یہ پیش کی کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو دوسرے سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے.یہ حصہ بھی بتاتا ہے کہ کسی نے دو سچائیوں کو بے موقع جوڑ دیا ہے کیونکہ جب ایک بالمقابل تجویز پیش کی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ پہلی تجویز سے زیادہ آسان اور سہل ہوا کرتی ہے.کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات منظور نہیں تو یوں منظور کر لو تو اس کے یہی معنے ہوا کرتے ہیں کہ اگر پہلی بات میں کچھ مشکلات ہیں تو یہ دوسری اس سے سہل ہے اسے مان لو مگر ہر عقلمند سوچ سکتا ہے کہ اس جگہ پہلی تجویز میں کچھ چیز تو کافر بھی دیتے تھے یعنی وہ مال دیتے تھے، بیٹی دیتے تھے، حکومت دیتے تھے اور مانگتے صرف یہ تھے کہ ہمارے معبودوں کو گالی نہ دو یہ نہیں کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو.لیکن دوسری تجویز جو منطقی طور پر اس سے سہل ہونی چاہیے اس میں وہ دیتے تو کچھ نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے معبود یعنی اللہ کی عبادت وہ پہلے ہی کیا کرتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے لیکن محمد رسول اللہ ؐ سے مانگتے وہ چیز ہیں جو پہلی تجویز سے زیادہ سخت ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
Page 241
سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو.یعنی دوسرے مطالبہ کے دونوں حصے پہلے مطالبے کے دونوں حصوں سے زیادہ سخت ہیں اور اس صورت میں اس کو متبادل تجویز کہنا نہایت حماقت اور بے وقوفی ہے پس یہ دیکھتے ہوئے کہ پہلی تجویز کا جواب ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے دے دیا تھا اور اسے ان تاریخی لفظوں میں ردّ کر دیا تھا کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لا کر کھڑا کر دو تب بھی میں ایک خدا کی عبادت نہ چھوڑوں گا اور تمہارے معبودوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں گا.اس کے معاً بعد دوسری تجویز پیش کرنے کی کوئی عقلمند جرأت ہی نہیں کر سکتا تھا اور یہ دیکھتے ہوئے کہ دوسری تجویز جو منطقی طور پر پہلی تجویز سے نرم ہونی چاہیے پہلی تجویز سے بدرجہا زیادہ سخت ہے اور اسے متبادل تجویز قرار دینا عقل کے بالکل خلاف ہے.ماننا پڑتا ہے کہ درحقیقت یا تو حضرت ابن عباس نے دو مختلف وقتوں میں یہ باتیں بتائی ہیں اور راوی نے سوچنے کے بغیر ان کو جوڑ کر ایک ہی روایت کے طور پر پیش کر دیا ہے یا یہ کہ کسی کم عقل راوی نے دو روائتیں مختلف لوگوں سے سن کر ان کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا ہے اور پھر ان کو ابن عباس ؓ کی طرف منسوب کر دیا ہے.چونکہ اس جگہ اس روایت کا ذکر آگیا ہے جس میں کفار نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم آپ کو دولت بھی دیں گے، بیوی بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے لیکن آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں نہ دیں اس لئے یہاں اس سوال کا جواب دینا بھی مناسب ہے کہ کیا ان کا یہ مطالبہ صحیح تھا.کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو گالیاں دیا کرتے تھے.ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اس میں معبودانِ باطلہ کے بارہ میں کہیں گالیاں نظر نہیں آتیں.بلکہ اگر نظر آتا ہے تو یہ کہ معبودانِ باطلہ کو گالیاں دینے سے اپنے اتباع کو بھی منع کر دیا ہے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ١ؕ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ (الانعام:۱۰۹) یعنی جن کی پرستش یہ لوگ خدا کے سوا کرتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو ورنہ یہ لوگ بے جانے بوجھے دشمنی کی وجہ سے اللہ کو گالیاں دیں گے.ہم نے اسی طرح ہر قوم کو اس کا عمل خوبصورت کر کے دکھایا ہے یعنی جب کسی کو چڑایا جائے تو وہ جواب دیتے وقت اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ جو کچھ میں جواب دیتا ہوں وہ خود میرے اپنے مسلمات پر بھی حملہ بن جاتا ہے بلکہ غصہ میں ایسا جواب دے جاتا ہے جو ایک مشترک وجود پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے.پس اگر تم ان کو جنہیں معبود سمجھا جاتا ہے گالیاں دو گے تو کفار غصہ میں آکر کہیں گے کہ تمہارا معبود بھی ایسا ہی ہے.حالانکہ درحقیقت تمہارا معبود اور ان کا معبود ایک ہی ہے یہ فعل ان کا جہالت پرمبنی ہوگا لیکن ان کی اس گالی کا محرک تم بن جاؤ گے اس لئے تم کو اس سے بچنا چاہیے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گالیاں نہیں دیتے تھے بلکہ گالیاں دینے سے آپ پر
Page 242
نازل ہونے والی کتاب روکتی تھی.پھر کفار کیوں کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی وجود کے متعلق کسی غلط مقام کا دعویٰ کیا جائے تو اس مقام میں جن خصوصیتوں کا پایا جانا ضروری ہو ان کا ردّ کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ اس غلط دعوے کی تردید نہیں ہو سکتی.مثلاً اگر کسی شخص کو غلط طور پر ڈاکٹر کہاجاتا ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ ڈاکٹری کے کالج میں نہیں پڑھا.اور اس کو طب نہیں آتی اور یہ دونوں باتیں اس کی شان کو گرانے والی ہیں لیکن گالی نہیں کیونکہ ضرورت کے طور پر استعما ل کی گئی ہیں اور بطور دلیل کے استعمال کی گئی ہیں اور اس کے دعویٰ کو ردّ کرنے کے لئے اس کے بغیر چارہ نہیں.اسی طرح قرآن کریم میں معبودانِ باطلہ کے وہ نقائص بیان کئے گئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معبود نہیں ہو سکتے.اگر وہ نقائص بیان نہ کئے جاتے تو یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ معبود نہیں ہیں.پس ایسی بات کہناجس کے ذریعہ سے ایک غلط دعوے کی تردید مقصود ہو اور جس کے بغیر اس دعوے کی تردید نہ ہو سکتی ہو گالی نہیں ہوتی بلکہ اظہار ِ حقیقت ہوتا ہے.لیکن ایسی بات کہنا جو حقیقت کے خلاف ہو یا جس کے کئے بغیر بھی دوسرے کی غلطی ثابت ہو سکتی ہو اور جس کے کہنے سے بلاوجہ دوسرے کا دل دکھانا مقصود ہو وہ گالی کہلاتی ہے.قرآن کریم میں ایسا کوئی لفظ معبودانِ باطلہ کے متعلق استعمال نہیں کیا گیا.اس زمانہ میں بھی بانی سلسلہ احمدیہ نے علماء کی بعض غلطیوں کی طرف انہیں توجہ دلائی ہے اور وہ اپنی کثرت کے گھمنڈ میں لوگوں کو اشتعال دلادیتے ہیں کہ بانی ٔ سلسلہ احمدیہ نے علماء یا مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں حالانکہ نہ انہوں نے علماء اور مسلمانوں کو کچھ کہا ہے نہ انہوں نے کوئی گالی دی ہے.انہوں نے صرف ان علماء اور ان مسلمانوں کے متعلق کچھ کہا ہے جنہوں نے بانی ٔ سلسلہ احمدیہ کے متعلق ظلم اور تعدی اور بہتان سے کام لیا اور گالیوں کے انبار لگا دیئے.نیز آپ نے صرف اظہار ِ حقیقت کیا ہے.گو بعض جگہ پر اظہار حقیقت کے لئے آپ نے ایسے الفاظ ضرور استعمال کئے ہیں جو عربی محاورہ کے مطابق ایک استعارہ ہیں.اور دوسرے صلحاء نے بھی ان کو اسی رنگ میں استعمال کیا ہے لیکن مفسد مولوی جہلاء کو غصہ دلانے کے لئے ان کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس کو سن کر عوام الناس چِڑ جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو اسلامی لٹریچر اور اسلامی بزرگوں کی تحریرات سے مَس ہے اور جو عربی جانتے ہیں.وہ جانتے ہیں کہ وہ الفاظ استعارۃً استعمال ہوئے ہیں اور طبیعتوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کے لئے صرف نشتر کے طور پر استعمال ہوئے ہیں.(ج)اس آیت کے متعلق مفسرین میں ایک عجیب اختلاف پیدا ہوا ہے.بعض مفسرین نے جن میں علامہ قرطبی اور دوسرے کئی مفسرین شامل ہیں کہا ہے کہ بعض لوگوں نے قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کی تفسیر یہ کی ہے کہ قُلْ
Page 243
لِّلَّذِیْنَ کَفَرُوْا تو کافروں سے کہہ دے.لیکن یہ تعبیر غلط اور خدا تعالیٰ پر افتراء ہے.اور اس سورۃ کے مضمون کو کمزور کرنے کی غرض سے ہے.اور اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو باطل کرنے کے لئے ہے کہ خدا تعالیٰ کا نبی مشرکوں کو سامنے بلا کر حقارت کے ساتھ مخاطب کر کے رسوا کرے اور ان پر ایسا الزام لگائے جس سے ہر عقلمند بچنے کی کوشش کرتا ہے( تفسیر قرطبی سورۃ الکافرون ).علامہ قرطبی اور ان کے ہم خیال دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ قُلْ لِّلَّذِیْنَ کَفَرُوْا کے الفاظ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر حکم کا مخاطب کسی ایک شخص کو بھی کہہ دے یا کسی مجلس میں تقریر کر دے.تو ایسا کرنے سے یہ حکم پورا ہو جائے گا لیکن قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کے الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ان کو سامنے بٹھا کر کہا جائے کہ اے کافرو تم ایسے ہو اور ایسے ہو.جہاں تک قرأت کا سوال ہے میرے نزدیک یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں قُلْ لِّلَّذِیْنَ کَفَرُوْا ہے یا قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ہے کیونکہ کوئی ایسی قرأت میرے علم میں نہیں ہے.اور کتب قرأت میں ہم نے کوئی ایسی قرأت نہیں دیکھی.پس جس نے قُلْ لِّلَّذِیْنَ کَفَرُوْا کہا ہے اس نے بھی قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کے معنوں سے درحقیقت ایک استدلال کیا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کا مفہوم اتنا ہی ہے کہ کافروں سے کہہ دو.یہ مفہوم نہیں کہ ان کو بلا کر ذلیل کرو اور ان پر سختی کرو اور جنہوں نے يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کے الفاظ پر زور دیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ اَیُّھَا تنبیہ کے لئے ہوتا ہے اس لئے ان الفاظ میں اس امر پر زور دیا گیا ہے کہ کفار کو مخاطب کر کے ان پر اچھی طرح یہ بات واضح کر دو اور ان کی بے عقلی کو ان پر ظاہر کردو.میرے نزدیک یہ بحث محض ایک لفظی بحث ہے اس میں کوئی حقیقت مخفی نہیں.کیونکہ مفہوم تو آگے بیان ہی ہے اور اس میں زور بھی ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہے.خواہ یہ مضمون کافروں کو کسی کے ذریعہ سے پہنچا دیا جائے.خواہ بلا کر کہہ دیا جائے.اس کا مفہوم تو ان کو پہنچ ہی جاتا ہے.اور اس زور سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا جو اس عبارت میں پایا جاتا ہے.کیونکہ جس شخص کو یہ پیغام پہنچایا جائے گا کہ جس چیز کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے اور نہ ایسا ممکن ہوسکتا ہے اسے اور زیادہ دھتکارنے کی اور کیا صورت باقی رہ جاتی ہے؟ یاد رہے کہ يٰۤاَيُّهَا کے الفاظ ہمیشہ زور دینے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے.لیکن کسی تذلیل یا تحقیر کا سوال نہ اَیُّھَا کے الفاظ میں ہے نہ اَلَّذِیْنَ کَفَرُوْا کے الفاظ میں ہے.تذلیل اور تحقیر تو انسان کا فعل کرتا ہے ہمارے کہنے سے کیا بنتا ہے.جب کفار کے فعل کی صورت کو بیان کر دیا گیا اور جب اپنے عقیدہ کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا تو اپنی خوبی اور ان کی ضد کا ذکر آپ ہی آگیا.
Page 244
ان مفسرین نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خود بھی تو اس مضمون کو محدود کر کے کمزور کر رہے ہیں.کیونکہ جب یہ مضمون کفار مکہ کے چند افراد کے لئے مخصوص تھا تو پھر وہ کون سا مضمون اس میں پایا جاتا ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کوئی عقلمند ایسا نہیں کر سکتا.اس سورۃ میں تو یہی بتایا گیا ہے کہ تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں اور تم اس طریق سے عبادت نہیں کرتے جس طریق سے میں کرتا ہوں.اس ادّعا اور اس بیان میں کون سی دلیل دی گئی ہے جس سے معلوم ہو کہ کوئی معقول آدمی ایسا نہیں کر سکتا.پہلے سورۃ کا مضمون ایسا بتانا چاہیے جو ایسے امور پر دلالت کر رہا ہو جن سے کفار کی سُبکی ہوتی ہو تو پھر بے شک یہ مفہوم نکلے گا.خالی اَیُّھَا کے الفاظ سے کس طرح نکل آئے گا.اور اس مفہوم کے پیدا کرنے میں تو وہ آپ روک بنے ہیں کہ اس کو چند افراد کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے.اور سورۃ کا خلاصہ صرف اتنا بن گیا ہے کہ اے چند لوگو! نہ تم میر ی سنتے ہو نہ میں تمہاری سنتا ہوں تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ.اس میں کون سی دلیل عقلی ہے جس کی وجہ سے کفار کی بے عقلی اور بےوقوفی ثابت ہوتی ہو.یہی وجہ ہے کہ میں نے اتنا زور اس بات پر دیا ہے کہ یہ مضمون چند افراد کے ساتھ مخصوص نہیں اور اس کا وہ مفہوم نہیں جو مفسرین نے لیا ہے.کیونکہ صرف اسی صورت میں ہماری نظر اصل مضمون کی طرف جاتی ہے اور اس کی وسعت ہمارے سامنے آجاتی ہے.يٰۤاَيُّهَا کے متعلق یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عربی میں تنبیہ کا مفہوم یہ نہیں ہوا کرتا کہ کسی بری بات سے روکا جاتا ہے بلکہ اس میں محض توجہ دلانے کے معنے ہوتے ہیں.قرآن کریم میں يٰۤاَيُّهَا کے الفاظ قریباً پچاس ساٹھ جگہ پر استعمال ہوئے ہیں.کسی جگہ پر ان الفاظ سے مجرموں کو مخاطب کیا گیا ہے تو کسی جگہ پر مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے.کسی جگہ پر مخالفین اسلام کو مخاطب کیا گیا ہے تو کسی جگہ پر تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا گیا ہے اور کسی جگہ پر رسولوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور کسی جگہ پر نبیوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور اس بات سے ظاہر ہے کہ اَیُّھَا کے معنے ڈانٹنے کے نہیں ہیں.بلکہ اَیُّھَا کا لفظ صرف توجہ دلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور توجہ انبیاء کو بھی دلائی جا سکتی ہے، توجہ مومنوں کو بھی دلا ئی جا سکتی ہے.توجہ مجرموں کو بھی دلا ئی جا سکتی ہے، توجہ کافروں کو بھی دلا ئی جا سکتی ہے اور توجہ تمام بنی نوع انسان کو بھی دلا ئی جا سکتی ہے، اسی طرح توجہ محبت کے موقع پر بھی دلائی جا سکتی ہے اور توجہ غصہ کے موقع پر بھی دلائی جا سکتی ہے.مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا(الاحزاب:۴۶ ) یہ محبت کے اظہار کا موقع ہے.یہاں کسی ڈانٹ کا کوئی سوال ہی نہیں.صرف اس مضمون کی عظمت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اتنا بڑا انعام ہم نے تم پر کیا ہے.اسی طرح فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ
Page 245
لَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ (الـمآئدۃ:۴۲ )یہاں بھی ڈانٹنے کا کوئی موقع نہیں بلکہ ہمدردی کا مضمون ہے.پس يٰۤاَيُّهَا کے معنوں میں زجر اور توبیخ اور تحقیر اور تذلیل نہیں پائی جاتی.بلکہ محض مضمون کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کہہ کر بتایا گیا ہے کہ اے کافرو! جس مضمون کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں وہ نہایت اہم ہے مگر ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ مضمون جس کے متعلق خدا کہتا ہے کہ نہایت اہم ہے.ہم اس کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اے کافرو میں تمہاری نہیں سنتا تم میر ی نہیں سنتے.تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ.اس مضمون میں کون سی اہمیت ہے.آخر کوئی دلیل بیان ہونی چاہیے کہ کیوں تم میری نہیں سنتے اور کیوں میں تمہاری نہیں سنتا اور اس کے کچھ نتائج بیان ہونے چاہئیں.تب جا کر اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے.لیکن اس مضمون کو محدود کر کے انہی تینوں چیزوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے.لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.اس سورۃ کا مضمون ایسا ہے کہ الگ الگ آیتوں کی تفسیر کرنی مشکل ہے بلکہ اگر الگ الگ آیتوں کی تفسیر کی جائے تومیرے نزدیک مضمون غلط ہو جائے گا یا کم سے کم میں اپنے اندر ایسی طاقت نہیں پاتا کہ الگ الگ آیتوں کی تفسیر بھی کر وں اور وہ تسلسل بھی قائم رہے جو اس سورۃ کی آیتوں میں پایا جاتا ہے.اس لئے خواہ یہ کہہ لو کہ اس سورۃ کی آیتوں میں بڑا شدید اتّصال ہے یا یہ کہہ لو کہ مجھ میں قدرت نہیں ہے کہ میں ان کے مضمونوں کو الگ الگ بھی بیان کروں اور تسلسل بھی قائم رکھوں.بہرحال کوئی وجہ ہو میں مجبور ہوں کہ ساری سورۃ کی تفسیر اکٹھی بیان کروں.اس لئے بجائے الگ الگ آیتوں پر نوٹ لکھنے کے میں اسی آیت کے نیچے ساری آیتوں کے متعلق اکٹھا نوٹ لکھ دیتا ہوں.اس سورۃ میں ایک مضمون کو دو شکلوں میں ادا کیا گیا ہے.اور دو دفعہ دہرایا گیا ہے ایک حصہ مضمون کا یہ ہے کہ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا.اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے.اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ.نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کر چکے ہو.اور چوتھی بات یہ کہی گئی ہے کہ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ نہ تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں.بظاہر اس میں ایک مضمون کو دو دفعہ دہرادیا گیا ہے ایک حصہ کو تو الفاظ میں تغیر قلیل کر کے دہرایا گیا ہے.اور دوسرے حصہ کو جوں کا توں دہرا دیا گیا ہے.قرآن کریم میں تو تکرار نہیں ہوا کرتی.پھر ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ جن مفسرین نے اپنی تفسیر کی بنیاد اوپر کی روایتوں پر رکھی ہے انہوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ چونکہ کفار نے دو صورتوں میں اپنا سوال پیش کیا
Page 246
تھا اس لئے دو ہی دفعہ ان کو جواب دیا گیا ہے.دوسراجواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ تکرار تاکید کے لئے ہے اور ان کی طمع کو دور کرنے کے لئے ہے.اور تیسراجواب یہ دیا گیا ہے کہ پہلے دو جملے حال کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں اور دوسرے دو جملے استقبال کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں.اس لئے تکرار نہیں.یہ قول ثعلب اور زجاج کا ہے(تفسیر قرطبی وفتـح البیان سورۃ الکافرون) مگر اس کے خلاف زمخشری کہتے ہیں کہ لَاۤ اَعْبُدُ سے مراد مستقبل کی عبادت ہے.کیونکہ لا سوائے اس مضارع کے جس کے معنے استقبال کے ہوں کسی اور مضار ع پر داخل نہیں ہوتا.پس پہلے دوجملے (نہ کہ دوسرے دوجملے)مستقبل کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں اور دوسرے دو جملے (نہ کہ پہلے)ماضی کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں.علامہ زمخشری کے مخالفوں نے کہا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ کہ آخری دو جملے ماضی کی عبادت کی نفی کے لئے ہیں یہ درست نہیں.کیونکہ اسم فاعل منوّن(جیسا کہ اس آیت میں وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ ہے)جو فعل کا عمل کرتا ہو.وہ حال اور استقبال کے سوا کوئی معنے نہیں دیتا اور یہاں عَابِدٌ کا لفظ مَا پر فعل کا عمل کر رہا ہے اور اسی طرح دوسری آیت میں عٰبِدُوْنَ کا لفظ بھی مَا پر عمل کر رہا ہے.یعنی دونوں اسم فاعل فعل کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں.اس لئے قاعدہ کے رو سے ان کے معنے حال اور استقبال کے ہو سکتے ہیں.ماضی کے نہیں ہو سکتے(البحر المحیط سورۃ الکافرون) علامہ زمخشری کے ہم خیالوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جب حکایت کے طور پرمضمون بیان کیا جائے تو اس وقت ماضی کے معنے لینے جائز ہوتے ہیں.جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَ کَلْبُھُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَصِیْدِ ( الکہف: ۱۹) یہاں بَاسِطٌ اسم فاعل کا صیغہ ہے جو ذِرَاعَیْہِ کے لفظ پر عمل کر رہا ہے.لیکن باوجود اس کے اس کے معنے ماضی کے ہیں.حال اور مستقبل کے نہیں.بعض نے اس جگہ پر یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ.تو کیا وجہ ہے کہ جب پہلے جملہ میں مَا کے بعد عَبَدْتُّمْ ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا تو دوسرے جملہ میں مَاۤ اَعْبُدُ مضارع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ماضی کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا گیا.اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ماضی کے معنے اس جگہ پر نہیں لئے گئے.(البحر المحیط سورۃ الکافرون) علامہ زمخشری کے خیال کی تائید کرنے والوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار آپ کی بعثت سے پہلے بتوں کو پوجتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وقت شروع کی جبکہ آپ مبعوث ہوئے.اس لئے آپ کے متعلق مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے.ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا(روح المعانی و روح البیان سورۃ الکافرون) اس خیال کے مخالفوں نے پھر اس پر یہ جرح کی ہے کہ عبادت سے مراد یہ نماز تو نہیں جو
Page 247
ہم پڑھتے ہیں.بلکہ اصل عبادت خدا تعالیٰ کو ایک سمجھنا ہے اور سارے انبیاء اپنی عقلوں کے ذریعہ سے اپنی بعثت سے پہلے مؤحد ہی ہوا کرتے تھے.پس یہ کہنا درست نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس لئے حال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ بعثت سے پہلے خدائے واحد کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے.خدا ئے واحد کی عبادت کا عام مفہوم یعنی اس کی توحید کا اقرار اور اس پر اصر ار یہ بعثت سے پہلے بھی آپ میں موجود تھا.اس لئے جس طرح آپ کی بعثت سے پہلے کفار بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے آپ بھی اپنی بعثت سے پہلے خدائے واحد کی پرستش کیا کرتے تھے گو اس کی شکل اور تھی.اور شکل کے بدل جانے کی وجہ سے عبادت کو عبادت کے دائرہ سے خارج نہیں کیا جا سکتا.عیسٰیؑ اور موسٰی کی نماز اور تھی، نوحؑ کی اور تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تھی.لیکن پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ سب انبیاء خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے.جیسا کہ اوپر کے مضمون سے ظاہر ہے مفسرین کی ان تشریحات سے مضمون کچھ غلط سا ہو جاتا ہے اور پڑھنے والا یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ پھر اصل بات کیا ہے.میں اس کے متعلق ذیل میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں.لَا جس کے معنے نہیں کے ہوتے ہیں جب مضارع پر آئے تو اس کے معنے ائمہ ادب کے نزدیک مستقبل کے کردیتا ہے.سوائے مالک کے کہ ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں.چنانچہ وہ مثال دیتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں کہ جَآءَ زَیْدٌ لَا یَتَکَلَّمُ.زید آیا مگر وہ خاموش تھا بولتا نہ تھا (اقرب ) گویا لَا یتَکَلَّمُ اس جگہ ماضی کے معنوںمیں استعمال ہوا ہے.مالک کی رائے درحقیقت استثناء کی حیثیت رکھتی ہے.انہوں نے جس امر کی طرف توجہ دلائی ہے اس میں بعض خصوصیات ہیں.(۱)وہ لَا ایک دوسرے جملہ کے تتمہ کے طور پر استعمال ہوا ہے.(۲)وہ ایک ماضی کے ساتھ وابستہ ہے اور معنوں کے لحاظ سے حال ہے.گو زمانہ کے لحاظ سے حال نہیں.یعنی جس وقت کے متعلق ذکر کیا گیا ہے اس وقت وہ گذرنے والی حالت پر دلالت کرتا تھا نہ کہ کسی سابق میں گذری ہوئی حالت پر.ان سب دلائل کی وجہ سے ہم اس قسم کے استعمال کو قاعدہ کا ردّ کرنے والا نہیں کہیں گے.بلکہ یہ کہیں گے کہ جب صرف مضارع کے ساتھ لَا مستعمل نہ ہو بلکہ بعض اور قیود اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو وہ حال کے معنے بھی دے دیتا ہے.لیکن خالی مضارع کے ساتھ اس کا استعمال ہمیشہ استقبال کے معنے دیتا ہے.پس لَاۤ اَعْبُدُ کے معنے اس آیت میں یہی ہوں گے کہ میں کبھی بھی عبادت نہ کروں گا.دوسرا حرف ان آیات میں مَا کا استعمال ہوا ہے.مَا علاوہ نافیہ ہونے کے جس صورت میں کہ وہ حرف ہوتا ہے اسمیہ بھی ہوتا ہے.اور اس وقت وہ موصولہ کے معنے دیتا ہے.یعنی اس کے معنے ’’جو‘‘’’جس کی ‘‘کے ہوتے ہیں.عام طور پر یہ غیر ذوی الارواح کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی
Page 248
ذوی العقول کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے.یعنی انسانوں، فرشتوں اور خدا تعالیٰ کی ذات کے متعلق بھی.اس وقت اس کے معنے مَنْ کے سمجھے جاتے ہیں.جو لفظ جاندار اور عاقل اشیاء کے لئے عام طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی مَا حرفیہ جب فعل پر آئے تو اس کے معنے مصدر کے بنا دیتا ہے.قرآن کریم میںہے وَ اَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (مریم:۳۲) یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید میرے تمام زمانہ حیات کے لئے کی ہے اس جگہ مَا جو ماضی پر آیا ہے.اس نے ماضی کے معنے مصدر کے کر دیئے ہیں.اسی طرح جب عرب کہے گا لَا اَصْـحَبُکَ مَا دُمْتُ حَیًّا تو گو دُمْتُ فعل ہے.مگر اس کے معنے ہوں گے ’’زندگی تک‘‘یا ’’میرے زندہ رہنے تک ‘‘.آیات زیر تفسیر میں ’’مَا تَعْبُدُوْنَ‘‘’’مَاۤ اَعْبُدُ‘‘’’مَا عَبَدْتُّمْ‘‘ ’’مَاۤ اَعْبُدُ‘‘ چاروں جگہ یہ مصدری معنے بھی ہو سکتے ہیں اور مَا موصولہ کے معنے بھی اور پھر مَا کے عام معنے بھی جو غیرذوی العقول کے ہیں اور کبھی کبھار استعمال ہونے والے معنے بھی.یعنی ذوی العقول کی طرف اشارہ کرنے والے معنے.ان تشریحات کے رو سے آیت لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ کے معنے یوں ہو سکتے ہیں.میں کبھی عبادت نہیں کروں گا ان وجودوں کی خواہ جاندار عقل والے ہوں یا غیر جاندار عقل سے خالی جن کی تم عبادت کرتے ہو یا میں کبھی عبادت نہیں کروں گا تمہارے طریق عبادت کے مطابق(مصدری معنے ) وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ کے معنے ہوں گے.اور نہ تم عبادت کر سکتے ہو یا عبادت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس خدا کی عبادت کا جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا یہ کہ نہ تم عبادت کرو گے یا عبادت کر سکتے ہو اس طریق پر جس طریق پر میں عبادت کرتا ہوں.اور وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ کے معنے ہوں گے اور نہ میں عبادت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا عبادت کر سکتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو یا عبادت کرتے رہے ہو.اور وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ کے معنے یہ ہوں گے کہ نہ تم عبادت کر سکتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس کی عبادت کا جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا جس طریق سے میں عبادت کرتا ہوں.اب اگر یہ مختلف چسپاں ہونے والے معنے چاروں آیتوں میں لیں تو دوسری اور چوتھی آیت میں تکرار پایا جاتا ہے.پہلی اور تیسری آیت کے الفاظ الگ الگ قسم کے ہیں.ان میں تکرار واقعہ نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے برخلاف ہم یہ قرار دیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں فضول تکرار نہیں ہو سکتا.اور چونکہ مَا کے دو معنے ہو سکتے ہیں.موصولہ کے بھی اور مصدریہ کے بھی.اللہ تعالیٰ نے وسعت معانی پیدا کرنے کے لئے آیتوں کے پہلے جوڑے میں مَاموصولہ استعمال کیا ہے اور دوسرے جوڑے میں مصدریہ تو تکرار کا سوال اڑ جاتا ہے اس کے مطابق آیات کے
Page 249
یہ معنے ہو جاتے ہیں کہ میں کبھی عبادت نہ کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم کبھی عبادت کروگے نہ کر سکتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتاہوں.اور اسی طرح میں عبادت نہیں کروں گا یا عبادت نہیں کر سکتا اس طریق پر جس طریق پر تم عبادت کرتے ہو اور نہ تم عبادت کرو گے یا کر سکتے ہو اس طریق پر جس طریق پر میں عبادت کرتا ہوں.ان معنوں کے رو سے سب تکرار مٹ جاتی ہے اور ہر ہر لفظ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور اس کی واضح غرض اور مقصد نظر آتا ہے.گو یہ معنے عربی کے لحاظ سے بالکل واضح ہیں اور ہر ایک پر روشن ہونے چاہیے تھے مگر ایک خاص معنوں نے دماغ پر اس قدر غلبہ حاصل کر لیا تھا کہ پہلے مفسرین کا ذہن اس طرف نہیں گیا.یہ سہرا ابو مسلم کے سر ہے کہ اس نے ایک واضح نحوی مسئلہ کو یہاں چسپاں کر کے تکرا رکے اعتراض کو دور کر کے اس سورۃ کے معنوں کو بادل کے ٹکڑہ تلے سے نکال لیا(البحـر المحیط سورۃ الکافرون) یہ وہی شخص ہے جو مرتد اور زندیق خیال کیاجاتا ہے.لیکن کبھی کبھی قرآن کریم کی ایسی تفسیر اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ شک پڑجاتا ہے کہ اس کا ایمان تعصب کی چادر تلے تو نہیں ڈھانپ دیا گیا.یہی وہ منفرد شخص ہے جس نے قرآن کریم میں نسخ کا انکار کیا ہے گو اس نے صرف دعویٰ کیا ہے(تفسیـر کبیر لامام رازی زیر آیت مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ....) جس طرح سر سید علی گڑھی نے وفات مسیحؑ کا صرف دعویٰ کیا تھا اور حضرت مسیح موعودعلیہ السلام نے نسخ قرآن کو بدلائل بیّنہ ردّ کیا ہے اسی طرح جس طرح وفاتِ مسیحؑ کو بدلائل بیّنہ ثابت کیا ہے.اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ ان پہلے دو شخصوں نے ان مضامین میں ستارہ ٔ صبح کو دیکھ کر قیاس کیا مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورج کو ہماری آنکھوں کے آگے لا کھڑا کیا.فَـجَزَاہُ اللہُ خَیْرًا عَنِ الْمُسْلِمِیْنَ وَالنَّاسِ کُلِّھِمْ وَاَخْزٰی اَعْدَاءَہٗ وَمَعَانَدِیْہِ.سورۂ کافرون کے متعلق جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کا چوتھا حصہ ہے.بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ چند آیتوں کی ایک سورۃ ہو اور اسے قرآن کریم کا چوتھا حصہ قرار دے دیا جائے.بہر حال اس سے یہ تو مراد نہیں ہو سکتی کہ یہ سورۃ قرآن کریم کے حجم کے لحاظ سے اس کا چوتھا حصہ ہے.یہی مراد ہوسکتی ہے کہ اس میں اتنے اہم مطالب آگئے ہیں کہ گویا یہ قرآن کریم کا چوتھا حصہ ہے.چنانچہ آگے چل کر ہم نے جو اس سورۃ کی تفسیر کی ہے اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس چھوٹی سی سورۃ میں اتنے وسیع مطالب بیان کر دیئے گئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسے قرآن کریم کا چوتھا حصہ قرار دیا ہے تو اس میں کسی قسم کے مبالغہ سے کام نہیں لیا.
Page 250
پھر علاوہ اہم مطالب کے ذکر کے اس سورۃ کو بعض اور خصوصیات بھی حاصل ہیں جو کسی اور سورۃ کو حاصل نہیں.وہ خصوصیات یہ ہیں.اوّل وہ مضمون جو اس سورۃ کے پہلے حصہ میں بیان ہوا ہے اور وہ مضمون جو اس سے پہلی سورۃ یعنی سورۂ کوثر میں بیان ہوا ہے آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کریم میں اور کوئی سورۃ ایسی نہیں ہے جس کی ابتدائی آیتیں پہلی سورۃ کے تمام مضامین کا نتیجہ کہلا سکیں.صرف یہی ایک سورۃ ہے جس کی ابتدائی آیات پہلی سورۃ کے تمام مضامین کا نتیجہ ہیں.دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد سورۃ آئی ہے یعنی سورۂ نصر اس کے سب مضامین کلی طور پر اس سورۃ کے بیان کردہ دعاوی کی دلیلیں ہیں.گویا اس سے پہلی سورۃ بھی اس کے دعاوی کی دلیل ہے اور اس کے بعد کی سورۃ بھی اس کے دعاوی کی دلیل ہے.مزید بر آں یہ کہ اس سورۃ کی آخری آیت بھی اس کے دعاوی کی دلیل ہے جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا.یہ ایسی خصوصیات ہیں جو قرآن کریم کی کسی اور سورۃ کو حاصل نہیں.الغرض اس کو قرآن کریم کا چوتھا حصہ قرار دینا بالکل صحیح اور درست ہے.اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے.اب میں اس کی کچھ مزید تشریح کرتا ہوں.اس سورۃ کی پہلی آیتیں یہ ہیں کہ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ.لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ.وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ.وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ.یعنی اے کفار جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان بتوں کی میں کبھی پوجا نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھی کریں گے اور جس طریق عبادت کو تم بجا لاتے ہو میں اس طریق عبادت کو کبھی نہیں بجا لاؤں گا اور نہ میرے ساتھی اس طریق عبادت کو بجا لائیں گے اور نہ تم اس ہستی کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ تم اس طریق عبادت کے مطابق عمل کرو گے جس طریق عبادت کے مطابق میں عمل کرتا ہوں.بظاہر یہ ایک تعلّی معلوم ہوتی ہے جو قرآن کریم کی شان کے خلاف نظر آتی ہے.قرآن کریم میں حضرت شعیب ؑ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفوں سے کہا کہ مَا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا( الاعراف:۹۰)یعنی میں اپنے دین سے کبھی مرتد نہیں ہوں گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے.مگر اس سورۃ میں حضرت شعیب ؑ کے طریق کے خلاف یہ کہا گیا ہے کہ یہ قطعی طور پر ناممکن بات ہے کہ میں یا میرے ساتھی کبھی بھی تمہارے معبودوں کی عبادت کریں.یا تمہارے طریق عبادت کو اختیار کریں.اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم کبھی
Page 251
ہمارے معبود کی عبادت کرو یا ہمارے طریق عبادت کو اختیار کرو.جہاں تک تاریخی واقعات کا سوال ہے یہ تو درست ہے کہ نہ صحابہ ؓنے کبھی بتوں کی پوجا کی اور نہ کبھی کفار کے طریق عبادت کو اختیار کیا.مگر دوسرا حصہ تاریخی شواہد کے خلاف معلوم ہوتا ہے.کیونکہ ہزار ہاکفار نے ایمان لا کر خدائے واحد کی بھی عبادت کی اور مسلمانوں کے طریق عبادت کو بھی اختیار کیا.پس بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون غلط ہو گیا.مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ کفار کے بڑے بڑے سردار مراد ہیں لیکن یہ بھی غلط ہے جیسا کہ اس سورۃ کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے.پس لازماً ان آیات میں کسی اور مضمون کا ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں اور مشرکوں کی فطرت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ مسلمان فطرتاً توحید کی طرف مائل ہے اور کافر نے ایک لمبی رسم و عادت کی وجہ سے مشرکانہ فطرت پالی ہے.اس لئے وہ اپنی عادت اور رسم کی وجہ سے شرک کی طرف تو مائل ہو سکتا ہے لیکن توحید کی طرف نہیں جا سکتا.سورۃ کوثر میں یہ مضمون تھا کہ اے محمد رسول اللہ ؐ ہم نے تجھ کو دین و دنیا میں بہتات بخشی ہے اور جہاں اس میں روحانی فتوحات کا ذکر تھا وہاں دنیوی فتوحات کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ تیری نسل یعنی تیرے مذہب پر چلنے والے لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے.جس میں گویا اس آیت کا مضمون تھا کہ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ یعنی ہمیشہ ہی آپ کے تابعین دنیا میں موجود رہیں گے جو شرک سے بیزار ہوں گے.پس لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ تعلّی نہیں بلکہ سورہ ٔ کوثر میں جو خدا تعالیٰ نے خبر دی تھی اس کا اظہار ہے.اور یہ حضرت شعیبؑ کے طریق کے بھی خلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق ہے کیونکہ حضرت شعیب ؑ یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے طریق کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ خدا کی مشیت مجھ سے یہ نہ چاہے.یعنی جب تک خدا کی مشیت مجھ سے اس مذہب پر قائم رہنے کامطالبہ کرے گی میں ہرگز اس مذہب کو نہیں چھوڑوں گا.اور سورۂ کوثر نے خدا کی مشیت بتا دی ہے کہ محمد رسول اللہ ؐ اور ان کے اتباع ہمیشہ توحید پر قائم رہیں گے.پس لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ اس کی تفسیر ہے اور سورۂ کوثر اس دعویٰ کی وجہ ہے.پھر سورۂ کوثر کے آخر میں فرمایا تھا کہ اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ.جو لوگ تیرے دشمن ہیں ان کی اولادیں ان کی اولادیں نہیں رہیں گی.یعنی روحانی طور پر وہ ان کی اولاد سے خارج ہو جائیں گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیں گی.اس حصہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ والا مضمون درست نہیں.کیونکہ جب کفار کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی تو لازمی طور پر وہ اس طریق پر عبادت کرنے لگ
Page 252
جائیں گی جس طرح مسلمان کرتے تھے.پس جہاں تک اس پیشگوئی کا سوال ہے وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ سے یہ نہیں نکل سکتا کہ قرآن جھوٹا نکلا.کیونکہ اس سے پہلی سورۃ نے ہی بتا دیا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ کفار اور ان کی اولادیں محمد رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو اختیار کر لیں گی.اور اس طرح وہ اپنے باپ دادا سے کٹ جائیں گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بن جائیں گی.جیسے عاص کا بیٹا عمرو مسلمان ہوا، ولید کا بیٹا خالد مسلمان ہوا، ابو جہل کا بیٹا عکرمہ مسلمان ہوا اور ابو سفیان خود مسلمان ہو گیا.پس درحقیقت وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ میں یہ پیشگوئی تھی کہ مکہ والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار نہیں کریں گے.ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ پیشگوئی جھوٹی نہیں نکلی.کیونکہ وہ مسلمان اپنی مرضی سے نہیں ہوئے بلکہ اِنَّ شَانِئَکَ ھُوَ الْاَبْتَرُ کی پیشگوئی کے ماتحت خدا تعالیٰ نے ان کو پکڑ کر مسلمان کیا اور خدا ئی تصرف کے ماتحت وہ ایمان لائے.پس عرب کا مسلمان ہو جانا قرآن کریم کے دعویٰ کے خلاف نہیں بلکہ قرآنی دعویٰ کی تصدیق ہے.اسی طرح میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس سورۃ کے بعد کی جو سورۃ ہے وہ بھی ان دعاوی کی دلیل ہے جو قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کے شروع میں بیان کئے گئے ہیں.قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ کے بعد کی یہ سورۃ ہے کہ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ.وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا.فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ١ؔؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا.یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تجھے حاصل ہو گی اور عرب پر غلبہ تجھے عطا ہو جائے گااور تو دیکھے گا کہ فوج در فوج عرب لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے.یہ آیت بھی سورۃ کافرون کی اس پہلی آیت کی دلیل ہے کہ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ.لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ یہ ظاہر ہے کہ جب باوجود کمزوری کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ دشمنان اسلام پر فتح بخشے گا اور ہزاروں ہزار آدمی مسلمان ہو جائیں گے تو اس نشان کے دیکھنے کے بعد کوئی مسلمان کفار کی طرف جا ہی کس طرح سکتا ہے.یہ تو روحانی بات ہوئی.ظاہری سبب کو بھی اگر دیکھو تو انسان اگر کسی کی طرف جاتا ہے تو لالچ کی وجہ سے جاتا ہے.جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور کفار خود مسلمانوں کے محتاج ہو جائیں گے تو ایسا کون بے وقوف مسلمان ہوسکتا ہے جو ان مقہور اور مغلوب کفار کے ساتھ ملے اور فاتحین کا ساتھ چھوڑ دے؟ پس سورۂ کوثر بھی جو اس سے پہلے ہے اور سورۂ نصر بھی جو اس کے بعد ہے دونوں سورۂ کافرون کی پہلی آیتوں کے لئے بطور دلیل ہیں.اسی طرح اس سورۃ کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ اس کا بھی حل اِذَاجَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ
Page 253
سے ہوجاتا ہے.یعنی کفار اپنی فطرت کے لحاظ سے تو شرک پر ہی قائم تھے.مگر جب نصرت اور فتح کے ذریعہ سے اسلام کی صداقت روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی تو ان کو حالات نے مجبور کر کے اسلام کی طرف دھکیل دیا.پس باوجود ان کے اسلام لے آنے کے وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ والی آیت جھوٹی نہیں ہوئی بلکہ سورۂ کوثر بھی سچی ہوئی، سورہ ٔنصر بھی سچی ہوئی اور سورۂ کافرون بھی سچی ہوئی.لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِؒ۰۰۷ (اوپر کا اعلان نتیجہ ہے اس کا کہ )تمہارا دین تمہارے لئے (طریق کار مقرر کرتا) ہےاور میرا دین میرے لئے (طریق کار مقرر کرتا )ہے.حلّ لُغات.دِیْنٌ.دِیْنٌ کے عربی زبان میں مندرجہ ذیل معنے ہیں.(۱) اَلطَّاعَۃُ.فرمانبرداری(۲) اَلسُّلْطَانُ وَالْمُلْکُ وَالْـحُکْمُ.غلبہ، بادشاہت اور حکومت(۳) اَلسِّیْرَۃُ.طریقہ.مذہب اور لوگوں سے معاشرت کی کیفیت.(۴) اَلتَّدْبِیْرُ.تدبیر کرنا (۵) اِسْـمٌ لِـجَمِیْعِ مَا یُعْبَدُ بِہِ اللہُ.دین نام ہے ان تمام طریقوں کا جن کے ذریعے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے.مثلاً مسلمانوں میں نماز پڑھنایا حج بیت اللہ کے لئے جانا یا اموال کی مقرر ہ مقدار پر ایک خاص نصاب سے غریبوں اور مسکینوں کے لئے زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت قرار دیا جاتا ہے.یہ طریق عبادت عربی زبان کے لحاظ سے دین کہلائے گا.اسی طرح ہندوؤں کے طریق عبادت کی جو بھی شکل ہو وہ دین کہلائے گی.یہودیوں اور زرتشتیوں وغیرہ کے طریق عبادت کی جو بھی شکل ہو وہ دین کہلائے گی گویا عبادت الٰہی خواہ کسی طریق سے کی جائے اس کا نام دین ہوتا ہے.(۶)اَلْمِلَّۃُ.نظام جماعت (۷)اَلْوَرَعُ.بدیوں اور ممنوعات سے بچنا(۸)اَلْمَعْصِیَۃُ.اطاعت سے نکلنا (۹)اَلْـحَالُ.حالت یا کیفیت (۱۰)اَلشَّاْنُ (ا) ایک خاص حالت.شان کے معنے حالت کے ہوتے ہیں.لیکن اَلشَّاْنُ کا لفظ عام حالت سے کسی قدر بلند معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے.جسے ہمارے ملک میں بڑی شان کہتے ہیں (ب)بہت ہی اہم امر (۱۱) اَلْعَادَۃُ.عادت(اقرب) تفسیر.لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَ لِيَ دِيْنِ میں کفار کی عبادت اختیار نہ کرنے کی دلیل کا بیان ہے سورۂ کافرون کی پہلی پانچ آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ
Page 254
اعلان کر دیں کہ کفار کے ساتھ ان کا اتحاد فی العبادۃ ناممکن ہے.زیر تفسیر آیت لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ میں ایسا اعلان کرنے کا سبب بتایا گیا ہے.اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا یہ اعلان دھینگا مشتی کا فعل نہیں نہ کسی عناد کے نتیجہ میں ایسا کیا گیا ہے.بلکہ یہ اعلان اس بات کا نتیجہ ہے کہ کفار کا دین ان کے لئے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کا دین ان کے لئے عبادت کا اور طریق مقرر کرتا ہے.اور چونکہ ہر دو طریق کار میں زمین و آسمان کا فرق ہے.اس لئے دونوں فریق کا اجتماع فی العبادۃ ناممکن ہے.سورۂ کافرون کی ابتدائی آیات میں پہلے ایک اصولی فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے.اور پھر اس اعلان کی دلیل لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے.یہی طریق بیان ہماری زبان میں بھی پایا جاتا ہے.چنانچہ ہمارے ملک میں کہتے ہیں کہ فلاں بات اس طرح ہے کیونکہ فلاں نے یوں کہا ہے.یعنی کلام کا آخری حصہ پہلے حصہ کے لئے وجہ اور سبب ہوتا ہے اور پہلا حصہ ایک نتیجہ ہوتا ہے جس کی بنیاد دوسرے حصہ پر رکھی جاتی ہے.عربی زبان میں چونکہ اختصار کو ملحو ظ رکھاجاتا ہے اس لئے بعض اوقات ان الفاظ کو جو ’’چونکہ‘ ‘اور’’کیونکہ‘ ‘کا مفہوم ادا کرتے ہیں اڑا دیتے ہیں اور اس سارے مفہوم کو جملہ کی بندش سے ادا کیاجاتا ہے.یہی طریق زیر تفسیر آیت میں اختیار کیا گیا ہے.پہلے فرمایا قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ.لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ.وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ.وَ لَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ.یعنی ہم ہر زمانہ کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے زمانہ کے کفار کو کہتا چلا جائے.کہ وہ ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی کفار عبادت کرتے ہیں اور نہ کفار اس ہستی کی عبادت کر سکتے ہیں جن کی مومن عبادت کر رہا ہے اور نہ مسلمان اس طریقِ عبادت کو اختیار کرسکتا ہے جس کو کافر اختیار کئے ہوئے ہیںاور نہ کافر ہی مسلمان کے طریق عبادت کو اختیار کر سکتا ہے.اس اہم اعلان پر طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر اس اعلان کی ضرورت کیا پیش آئی.کیا کوئی ذاتی عناد ہے جو مسلمانوں اور کافروں میں ہے یا کوئی مناقشت اور جھگڑا ہے؟ فرمایا ایسا نہیں بلکہ اس اعلان کی وجہ یہ ہے کہ لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ مسلمانوں کا دین عبادت کا اور طریق پیش کرتا ہے اور کافر کا دین اور طریق پیش کرتا ہے.اور ہر دو طریق کار چونکہ بالکل متضاد اور مختلف ہیں.اس لئے دونوں گروہوں کا جمع ہونا ناممکن اورمحال ہے.گویا لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے فقرہ نے سابق آیات کے مفہوم کو کھول دیا اور وہ خلش اور سوال جو طبیعت میں پیدا ہوتا تھا کہ آخر اس اعلان میں براءۃ کی کیا ضرورت پیش آئی تھی اس کو جامع مانع الفاظ کے ساتھ حل کر دیا.
Page 255
حل لغات میں لفظ دین کے گیارہ معنے لکھے گئے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس آیت پر چسپاں ہوتے ہیں اور ان معنوں کو چسپاں کرنے کے بعد یہ مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس سوال کو جو قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ.لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ کے بعد طبعاً دل میں پیدا ہوتا تھا حل کر دیا گیا ہے.اور بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین مجبور ہیں کہ وہ اعلان کر دیں.کہ وہ اپنے مذہب کے اصول عبادت کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کی زبردست وجوہات ہیں جو اختصاراً لفظِ دین میں ہی بیان کر دی گئی ہیں اور جن کا ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں.لفظ دین میں آٹھ وجوہات کی طرف اشارہ اوّل.مسلمان جس قادر و قیوم ہستی کو مانتے ہیںان کے نزدیک اس کی اطاعت کے اصول اور ہیں اور کافروں کے نزدیک ان کے معبودوں کی پیروی کے اصول اور.(دِیْنٌ بمعنی اَلطَّاعَۃُ) دوم.مسلمانوں کا طریق عبادت اور ہے اور کافروں کا طریقِ عبادت اور.(دِیْن بمعنی مَا یُعْبَدُ بِہِ اللہُ) سوم.مسلمانوں کے اصول حکومت اور ہیں اور کافروں کے اور.(دِیْن بمعنی اَلسُّلْطَانُ وَالْمُلْکُ وَالْحُکْمُ) چہارم.مسلمانوں کے نزدیک تقویٰ اور نیکی اور بدی کی تعریف اور ہے اور کافروں کے نزدیک اور.اسی طرح مسلمانوں کے نزدیک حلال اور حرام کے اصول اور ہیں اور کافروں کے نزدیک اور (دِیْن بمعنی اَلْوَرَعُ وَالْمَعْصِیَۃُ) پنجم.مسلمانوں کے لوگوں سے معاشرت کے اصول اور ہیں اور کافروں کے اور(دِیْن بمعنی اَلسِّیْرَۃُ ) ششم.مسلمانوں کی تدبیر اور ہے اور کافروں کی اور (دِیْن بمعنی اَلتَّدْبِیْر) ہفتم.مسلمانوں کی عادات اور ہیں اور کافروں کی اور (دِیْن بمعنی اَلْعَادَۃُ) ہشتم.مسلمانوں کے روز مرہ کے کاموں کے اصول اور ہیں اور کافروں کے اور(دِیْن بمعنی اَلْـحَال) گویا لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کے نہ اصول ملتے ہیں اور نہ طریق کار.اس لئے مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان کہ ہم کفار کے ساتھ عبادت میں اتحاد نہیں کر سکتے بالکل صحیح اور درست ہے.اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا.کفار اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو صرف یہ کہ جو اصول اور طریق کار مسلمانوں نے اختیار کئے ہیں وہ غلط ہیں.اگر ان کی یہ بات ثابت ہو جائے تو بےشک اسلام کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے.لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام
Page 256
کے پیش کردہ اصول اور طریق کار صحیح اور اہم ہیں تو پھر مسلمانوں کا کافروں سے عبادت میں علیحدگی اختیار کرنا بالکل درست اور ایک ضروری امر ہو جاتا ہے.اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا.اور نہ اسے دھینگا مشتی کا فعل قرار دیا جاسکتا ہے.اب ہم اس مضمون کو جو مجملاً اوپر بیان کیا گیا ہے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں.تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ کس طرح لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کی آیت پہلی آیات کے لئے بطور سبب اور وجہ کے ہے اور یہ کہ کس طرح اس آیت کے مضمون سے پہلی آیات کے مضمون کو واضح اور مدلّل کیا گیا ہے.سو جاننا چاہیے کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ لفظ دِیْن کے پہلے معنے اَلطَّاعَۃ یعنی فرمانبرداری کے ہیں.ان معنوں کی رو سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے منکرو! چونکہ تمہارا طریق اطاعت اور اصول اطاعت اور میرا طریق اطاعت اور اصول اطاعت الگ الگ ہے اس لئے میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرسکتا اور تم میرے معبود کی اطاعت کرنے سے عملاً قاصر ہو.کیونکہ میرے اصول کے ماتحت بتوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی اور تمہارے اصول کے ما تحت خدائے واحد کی اطاعت نہیں ہو سکتی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے متبعین کے اصولِ اطاعت جو قرآن کریم سے مستنبط ہوتے ہیں یہ ہیں:.(۱)اس دنیا کا خالق و مالک خدائے واحد ہے اس کے احکام کی ہر شخص کو فرمانبرداری کرنی چاہیے.چنانچہ فرمایا فَاِلٰھُکُمْ اِلٰہٌ وَاحِدٌ فَلَہُ اَسْلِمُوْا(الحج : ۳۵)کہ اے لوگو! تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کی فرمانبرداری کرو.اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح فرمانبرداری کی جائے؟ کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے احکام دینے کے لئے خود دنیا میں نہیں آتا.اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک وہ خود دنیا میں نہیں آتا.لیکن وہ اپنے رسول بھیجتا ہے اور ان کے ذریعہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے.جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ١ٞ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ(الانعام:۱۰۴ )یعنی عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتیں.مگر وہ خود عقلوں تک پہنچنے کے ذرائع اختیار کرتا ہے.پس ایک رسول کی آواز سن کر یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جھوٹا ہے اور اس پر کلامِ الٰہی اور شریعت نازل نہیں ہوئی.اس صورت میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ رسول ہی نہیں ہے.اور اگر وہ سچا ہے اور اس پر الہامی شریعت نازل ہوئی ہے تو پھر اس کا انکار کر کے کوئی شخص خدا تعالیٰ کا مطیع نہیں کہلا سکتا.پس جو لوگ رسولوں کومان لیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں.اور جو انکار کرتے ہیں وہ صحیح راستہ سے بھٹک جاتے ہیں.اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ
Page 257
سے ہو.اس لئے جو ان کی اتباع کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کا متبع اور مطیع قرار پا سکتا ہے.اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہےوَ اَرْسَلْنٰكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا١ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ (النسآء:۸۰،۸۱) کہ اے محمد رسول اللہ ! اب ہم نے ساری دنیا کی ہدایت کا سامان تیرے ذریعہ سے کیا ہے.جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرے اسے چاہیے کہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)کی اطاعت کرے.کیونکہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے.پھر اسی مضمون کا اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کر دیا گیا ہے.فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ۠ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ( اٰل عمران:۳۲،۳۳) یعنی اے ہمارے رسول لوگوں کو یہ کھول کر سنا دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ بھی تم سے محبت کا اظہار کرے تو اس کا یہ طریق ہے کہ اس نے جو احکام میرے ذریعہ سے دنیا کے لئے بھیجے ہیں ان پر چلو اور میری پیروی کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گااور تمہاری کمزوریوں کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہاری ان کمزوریوں کے باوجود اپنا جلوہ تمہیں دکھائے گا اور اپنے فضلوں سے تمہیں ڈھانپ لے گا.پھر فرمایا قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ.کہ اے لوگو!اچھی طرح سے سن لو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو.اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعہ سے کرو.رسول چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیم لاتا ہے اس لئے جو اس پر ایمان لاتا ہے درحقیقت وہی خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے.پس ضروری ہواکہ احکام الٰہی کی وہ تفصیلات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کے مطابق اطاعت کی جائے اور اگر ان کے مطابق اطاعت نہ کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کہلا سکتی.پس جو الہامی شریعت کو مانتا ہے صرف وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مدعی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر عبادت بھی کی جا سکتی ہے.اسلام کا منکر چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا.اور جو شخص ایسے انسان کی روحانی امور میں اطاعت کرے گا اور اس کے ساتھ عبادت میں شریک ہو گا وہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف کرے گا.(۲)جس شخص کے دل میں محبت الٰہی کا جذبہ نہ ہو یا وہ کامل توحید پر نہ چلتا ہو اس کی بھی اطاعت نہیں کی جاسکتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ لَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ وَ كَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا (الکہف:۲۹) یعنی اے مخاطب تو اس شخص کی اطاعت مت کر جس کے دل میں ہماری محبت نہیں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا
Page 258
ہے.کیونکہ اس کی اطاعت کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ خدائے واحد سے دور لے جائے گا.پس یہ لازمی امر ہے کہ انسان اسی کی اطاعت کرے اور اسی کے ساتھ مل کر عبادت کرے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور ذکر ِ الٰہی کرنے کا وہ عادی ہو اور خدا تعالیٰ کی توحید پھیلانے کا وہ شغل رکھتا ہو.اگر اس میں ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی تو اس کی صحبت اور اس کا لیڈر ہونا لوگوں کو خدا تعالیٰ سے دور کرتا چلا جائے گا اور عبادت بجائے قائم ہونے کے ختم ہو جائے گی.چونکہ کفار توحید کو نہیں مانتے.نہ ان کے دل میں محبت الٰہی کا جذبہ ہے.اس لئے مومنوں کا ان سے اتحاد فی العبادۃ نہیں ہو سکتا.(۳)جو شخص بجائے واقعات پر بنیاد رکھنے کے صرف قسمیں کھا کر اپنے دعویٰ کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ تعاون کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَّھِیْنٍ ( القلم:۱۱) یعنی اے مخاطب ہر قسم کھانے والے کی پیروی مت کر.گویا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر بات واقعات و حقائق پر مبنی ہونی چاہیے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْۤ اَدْعُوْۤا اِلَى اللّٰهِ١ؔ۫ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ (یوسف:۱۰۹) یعنی ہمارے رسول یہ اعلان کر دے کہ میں اور میرے متبعین اپنے دعویٰ کے ساتھ شواہد، بیّنات اور دلائل رکھتے ہیں اور ہماری ہر بات حقائق و واقعات پر مبنی ہے.پس ہر بات واقعات پر مبنی ہونی چاہیے.خالی قسموں پر نہیں.بےشک قرآن مجید نے بھی قسمیں کھائی ہیں.لیکن قرآن کریم نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ درحقیقت بطور شہادت کے ہیں.مثلاً فرمایا وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ (البروج :۲) کہ ہم قسم کھاتے آسمان کی جو بروج والا ہے.یعنی ہم شہادت کے طور پر آسمان کو پیش کرتے ہیں جس میں بہت سے مدارج ہیں.اس بات کی تائید کے لئے کہ آسمان روحانی بھی مختلف مدارج رکھتا ہے یعنی روحانی ترقیات بھی مختلف درجوں میں تقسیم ہیں.اور ان سب کا مدّ ِنظر رکھنا ضروری ہے.اگر تم اس پر غور کرو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ مختلف زمانوں میں انسانوں کی ضرورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شریعتیں کیوں بھیجیں.اگر اس امر کو سمجھ لیاجائے تو تمہیں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا.لیکن اگر اس نکتہ کو نہ سمجھو گے تو تمہارے دل میں فوراً سوال پیدا ہو گا کہ ابراہیمؑ کے بعد موسٰی کی کیا ضرورت تھی اور موسٰی کے بعد عیسیٰؑ کی کیا ضرورت تھی اور پھر عیسیٰؑ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے؟ پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین چونکہ اپنی باتوں کی بنیاد واقعات، دلائل اور شواہد پررکھتے ہیں.اس لئے ان کا کفار سے اتحاد فی العبادۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.کیونکہ وہ اپنی باتوں کی بنیاد واقعات پر نہیں
Page 259
رکھتے بلکہ مطلق قسموں پر رکھتے ہیں.جن کا واقعات و حقائق سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا.(۴)جو شخص شریعت ِ الٰہی کی ضرورت کو تسلیم نہ کرتا ہو وہ بھی خدا تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ اپنی کرتا ہے.اس لئے ایسے شخص کے پیچھے چلنے والا بھی درحقیقت حقیقی عبادت نہیں کرتا.بلکہ عبادت سے دور چلا جاتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْھُمْ اٰثِمًا اَوْ کَفُوْرًا (الدھر:۲۵) اے مخاطب خدا تعالیٰ کی شریعت کے خلاف چلنے والے اور اس کے احکام کی نافرمانی کرنے والے کی اطاعت تمہیں خدا سے دور پھینک دے گی.اس اصل کے ماتحت جب کفار شریعت ِ الٰہی کے خلاف چل رہے ہیں تو ان سے اتحاد فی العبادۃ کر کے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے.سوائے اس کے کہ انسان خدا تعالیٰ سے دو رچلا جائے.(۵)بعض لوگ ایک دفعہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے صداقت کو مان لیا.لیکن پھر اپنا رُخ بدلتے رہتے ہیں ایسے انسانوں کی اطاعت بھی اسلامی اصول کے مطابق اطاعت نہیں کہلا سکتی اور نہ ان کی عبادت حقیقی عبادت کہلا سکتی ہے کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا.اگر ایمان ہوتا تو بدلتے کیوں؟ تبدیلی بتاتی ہے کہ ان کے اندر ایمان کامل نہیں.ایسے ہی لوگوں کا حا ل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.وَ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالرَّسُوْلِ وَ اَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ١ؕ وَ مَاۤ اُولٰٓىِٕكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ( النّور:۴۸) کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور ہم نے صداقت کو مان لیا لیکن پھر اپنا رخ بدل لیتے ہیں.یاد رکھو ایسے لوگ حقیقی مومنوں کی صف میں کھڑے نہیں ہوسکتے.کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ آپ کے ساتھ مل کر عبادت کر لیں.جیسا کہ اوپر کی روایات میں بعض کفار کا ذکر آیا ہے کہ وہ اس قسم کی بے ہودہ باتیں کر لیتے تھے چونکہ اسلام اس طریق کو درست نہیں سمجھتا اس لئے مومن ایسے لوگوں کے ساتھ متحد فی العبادۃ نہیں ہوسکتے.کیونکہ ایسے لوگ مخلص فی العبادۃ نہیں ہوتے اور اسلام پکا مومن انہی کو کہتا ہے جو کہ مخلص فی العبادۃ ہوں اور عبادت پر دوام اختیار کرنے والے ہوں، اور دلی یقین سے عبادت بجا لائیں.(۶)بعض الامر کی اطاعت بھی اطاعت نہیں کہلاتی بعض الامر کی اطاعت کے معنے یہ ہیں کہ وہ احکام جو اپنی مرضی کے مطابق ہوں ان پر عمل کر لیا جائے اور باقی کو ردّ کر دیا جائے.وہ شخص جو بعض الامر کی اطاعت کرتا ہے اس کے متعلق یہی سمجھاجائے گا کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر نہیں بلکہ اپنی مرضی پر چلتا ہے.اور اس کے صاف یہ معنے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی پوری اطاعت کرنے کے لئے تیار نہیں.صرف اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سَنُطِیْعُکُمْ فِیْ بَعْضِ الْاَمْرِ (مـحمّد:۲۷) اے لوگو! ہم تمہاری ان
Page 260
امور میں جو ہماری طبیعت کے مناسب حال ہیں اطاعت کرنے کو تیار ہیں.بہر حال ایسے لوگ جو ان امور میں اطاعت کریں جنہیں ان کے اپنے نفس بھی ماننے کے لئے تیار ہوں پوری طرح خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے نہیں کہلا سکتے.اس کے مقابلہ میں وہ شخص جو خدا تعالیٰ کی اطاعت اس لئے نہیں کرتا کہ اس کے احکام اس کی مرضی کے مطابق ہیں.بلکہ خواہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوں یا نہ ہوں وہ ان کی اطاعت کرتا چلا جاتا ہے.اس کا ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس اصل کے منکر ہوں اتحاد فی العبادۃ نہیں ہو سکتا.(۷)انسان اس لئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری نہ کرے کہ ان احکام پر چلنے کی وجہ سے اسے مادی فوائد حاصل ہو جائیں گے.مثلاً زکوٰۃ دے تو اس لئے نہیں کہ برادری سے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے بلکہ اس لئے دے کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی.جب تک اس اصل کے مطابق اطاعت نہ کی جائے انسان اپنے ایمان میں کامل نہیں کہلا سکتا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ یُؤْتُوْنَ الزَّکٰوۃَ وَیُطِیْعُوْنَ اللّٰہَ (التوبۃ:۷۱) یعنی کامل الایمان لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن مادی فوائد کے لئے نہیں.رشتہ داریاں بڑھانے اور تعلقات قائم کرنے کے لئے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کی غرض سے اور اس لئے کہ اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو جائے.یعنی جن امور کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو بھی وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے سرانجام دیتے ہیں یعنی کام خواہ ان کی فطرت کے مطابق ہوں یا قومی ضرورتوں کے مطابق ہوں.پھر بھی وہ ہر اچھا کام اس لئے نہیں کرتے کہ وہ کام ان کی فطرت کے مطابق ہے یا اس کے کرنے سے قوم خوش ہو جائے گی.بلکہ وہ اس لئے ان اعمال کو بجا لاتے ہیں کہ ان کا خدا خوش ہو جائے گا بہر حال وہ شخص جو اپنے اعمال کے بجا لانے میں اس نقطۂ نظر کو ملحوظ رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کیونکر عبادت کر سکتا ہے جو احکام الٰہی پر صرف اس لئے عمل کرتے ہیں کہ ان کو مادی یا قومی فوائد حاصل ہو جائیں.پھر یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ اَلطَّاعَۃُ کے معنے محض فرمانبرداری نہیں.بلکہ ایسی فرمانبرداری کے ہیں جو بشاشتِ قلب کے ساتھ کی جائے اور اس میں نفس کی مرضی اور پسندیدگی بھی پائی جاتی ہو.چنانچہ کہتے ہیں جَآءَ فُلَانٌ طَوْعًا اَیْ غَیْرَ مَکْرَہٍ (اقرب) یعنی فلاں شخص اپنی مرضی اور اختیار سے خود بخود آگیا نہ کہ جبر سے.اور طَوْعٌ کے مقابل پر کَرْہٌ کا لفظ بولا جاتا ہے جس کے معنے ہیں مَا اَکْرَھْتَ نَفْسَکَ عَلَیْہِ (اقرب) کہ انسان کوئی کام دل سے نہیں کرنا چاہتا بلکہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے اسے سر انجام دینے پر مجبو رہو جاتا ہے اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایسے کام میں بشاشت پیدا نہ ہوگی.طَوْعٌ مادہ سے بننے والے دوسرے کلمات اس مفہوم کو مزید واضح کر دیتے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں طَاوَعَہ
Page 261
فِیْہِ وَعَلَیْہِ مُطَاوَعَۃٌ.وَافَقَہٗ.کہ فلاں نے فلاں کی کسی امر میں مطاوعت کی.اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے دل سے اس کی موافقت کی.اس طور پر نہیں کہ اس موافقت کے لئے اس نے اپنے نفس پر جبر کیا ہو.اسی طرح کہتے ہیں طَاوَعَ لَہُ الْمُرَادُ.اَتَاہُ طَائِعًاسَھْلًا یعنی طَاوَعَ لَہُ الْمُرَادُ کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اس کا مقصد، اس کی مراد اور دلی خواہش بغیر تکلیف اورجدوجہد کے خود بخود پوری ہو گئی.پھر کہتے ہیں اَطَاعَہُ الْمَرْتَعُ اَیْ اِتَّسَعَ وَ اَمْکَنَہُ الرَّعْیَ یعنی جب اَطَاعَہُ الْمَرْتَعُ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ چراگاہ نہایت وسعت والی ہو گئی اور جانوروں نے بغیر کسی روک ٹوک کے چراگاہ کی گھاس سے اپنے پیٹوں کو بھر لیا.گویا اس میں مجازاً اس مضمون کو ادا کیا گیا ہے کہ چراگاہ اپنے آپ کو خود بخود پیش کر رہی تھی کہ اس سے جانور گھاس کھا کر سیر ہوسکیں.(اقرب) الغرض اَلطَّاعَۃُ کے معنے وضع لغت کے لحاظ سے خالی فرمانبردای کے نہیں.بلکہ اس فرمانبرداری کے ہیں جو پسندیدگی اور خوشی سے ہو نہ کہ جبر اور اکراہ سے.اور جو تکلف سے اطاعت کی جائے.یعنی عمل کرتے ہوئے اگر شرح صدر نہیں تو نفس کو عمل پر آمادہ کیا جائے اور بشاشت کا اظہار تکلف سے کیا جائے.اس کے لئے عربی زبان میں عام طور پر تَطَوَّعَ کا لفظ استعمال ہوتا ہے.قرآن کریم میں بھی آتا ہے فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْرًا فَھُوَ خَیْرٌ لَّہُ(البقرۃ:۱۸۵) کہ جو پورے شوق اور رضا سے اور شرح صدر سے نیکی نہیں کر سکتا اسے کم از کم تکلف سے ہی نیکی کرنی چاہیے اور نیکی کرتے وقت بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے.تاکہ یہ ظاہر نہ ہو کہ وہ اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے اور اگر ایسا کرے گا تو بہرحال اس کے لئے بہتری کے وہ راستے جو شرح صدر سے اعمال کرنے والے کے لئے کھلتے ہیں کھل جائیں گے.امام راغب اپنی کتاب مفردات میں لکھتے ہیں کہ تَطَوَّعَ کے گو اصل معنے تکلف سے کام کرنے کے ہیں مگر محاورہ میں غیر واجب کام کے نفلی طور پر کرنے کے بھی ہوتے ہیں.اس لئے اس آیت میں یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شخص نفلی طور پر نیکی کرے وہ اس کے لئے بہتر ہو گی.پس اطاعت کے اس مفہوم کے لحاظ سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے معنے یہ ہوں گے کہ اے منکرو! تمہارا اطاعت کا مفہوم اور ہے اور میرا اور ہے یعنی تم صرف ظاہری آداب بجا لانے کو اطاعت سمجھ رہے ہو اور میں اطاعت صرف اسے کہتا ہوں کہ بشاشتِ قلب سے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے جائیں اور ان کو بجا لاتے ہوئے انسان کو لذّت اور سرور محسوس ہو.
Page 262
یہ امر ظاہر ہے کہ احکام کی تعمیل میں بشاشتِ قلبی تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب مندرجہ ذیل امور موجود ہوں :.۱.احکام کے فلسفہ کو سمجھنا.۲.رحمت کا پہلو تعلیم میں غالب ہونا.۳.احکام کی تعمیل میں ایسے فوائد کا موجود ہونا جو اس تکلیف اور مشقت سے بڑھ کر ہوں جو اعمال کے بجالانے میں اٹھانی پڑتی ہے.۴.شریعت کا خود انسان کے حق میں مفید ہونا جس سے اسے اپنا مقصود نظر آجائے.یہ چاروں باتیں صرف اسلام میں پائی جاتی ہیں دوسرے مذاہب ان باتوں سے خالی ہیں.چنانچہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے سارے احکام فلسفہ پر مبنی ہیں.یعنی اسلام صرف کوئی حکم ہی نہیں دیتا بلکہ ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کہ اس حکم کی غرض کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے.تا ان احکام پر عمل کرنے والا اپنے دل میں ایک لذت محسوس کرے اور سمجھ لے کہ وہ لغو کام نہیں کر رہا.یا صرف حکم کی تعمیل نہیں کر رہا بلکہ ایسے حکم کی تعمیل کر رہا ہے جو اپنے اندر بے شمار انفرادی اور قومی فوائد رکھتا ہے.یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صرف حکم ہی نہیں بلکہ اس کا فلسفہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام کے ساتھ ساتھ آسمان سے نازل کیا گیا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ١ؕ وَ كَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (النسآء:۱۱۴) یعنی اے ہمارے رسول ہم نے تجھ پر احکام پر مشتمل ایک مکمل کتاب نازل کی ہے اور ان احکام کا فلسفہ بھی آسمان سے نازل کیا ہے اور تجھے وہ کچھ سکھایا ہے جو اس سے پہلے تو نہیں جانتا تھا اور تجھ پر اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے.پھر فرمایا کہ احکام کا یہ فلسفہ ہم نے صرف اپنے رسول پر اس کے ذاتی علم کے لئے ہی نہیں نازل کیا بلکہ اس لئے نازل کیا ہے تا وہ اپنے متبعین کو یہ فلسفہ بتائیں اور ان کو سمجھائیں.چنانچہ فرمایا.لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ١ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ( اٰلِ عمران:۱۶۵) یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے انہی کی قوم میں سے ایک رسول مبعوث کیا.جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے اور قوم کو ترقی کے ذرائع بتاتا ہے کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس سے پہلے نہایت ہی خطرناک گمراہی میں مبتلا تھے.پس اسلام کو دوسرے مذاہب کے مقابل پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ وہ اپنے احکام کی اغراض اور ان کے فلسفہ کو بھی بیان کرتا ہے تاکہ ان احکام کی تعمیل میں بشاشت قلبی
Page 263
قائم رہے اور تعمیل کرنے والوں کو لذت و سرور حاصل ہو.اور یہ فلسفہ ایک دو احکام میں نہیں بلکہ اسلام کے جملہ احکام میں اس کو مدّ ِنظر رکھا گیا ہے.اسلام کے سارے احکام کو گننا اور ان کے فلسفہ کو بیان کرنا ایک لمبا وقت چاہتا ہے.اس لئے یہ مضمون تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کیا جا سکتا.ہاں ذیل میں چند ایک مثالیں بیان کر دیتے ہیں تا مفہوم واضح ہو سکے.(۱)سو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ١ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ١ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ( التوبۃ: ۱۰۳) یعنی اے ہمارے رسول! مسلمانوں کے اموال میں سے کچھ رقم بطور صدقہ یعنی زکوٰۃ لیا کر تاکہ اس طریق سے تُو ان کو پاک کرنے اور ان کے اموال میں ترقی دینے کا راستہ کھول سکے اور ان کی قربانی کا مظاہرہ دیکھ کر ان کے لئے دعائیں کر سکے.کیونکہ تیری دعائیں ان کے لئے اطمینان و تسکین کا موجب ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تیری دعائیں سنتا اور قربانی کرنے والوں کے حالات کو خوب جانتا ہے.ان آیات میں پہلے فرمایا خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً کہ اے رسول ! مسلمانوں کے اموال سے زکوٰۃ لیا کر.اس کے بعد اس حکم کی غرض و غایت ان الفاظ میںبیان کی کہ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا.یعنی زکوٰۃ کی پہلی غرض تُطَهِّرُهُمْ کے ما تحت یہ ہے کہ انسان کا مال دوسروں کے حقوق ادا کرکے پاک ہو جائے کیونکہ تمام انسانوں کی دولت دوسرے لوگوں کی مدد سے کمائی جاتی ہے اور اس کمائی میں دوسروں کا حق شامل ہوتا ہے جو (باوجود مزدوری ادا کرنے کے)پھر بھی دولتمندکے مال میں باقی رہ جاتا ہے.مثلاً ایک مالدار آدمی ایک کان سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ کان کے مزدوروں کو ان کی مزدوری پوری طرح ادا بھی کر دے تو بھی وہ جو کچھ ان کو ادا کرتا ہے وہ ان کی مزدوری ہے.مگر قرآنی تعلیم کے مطابق وہ لوگ بھی اس کان میں حصہ دار تھے.کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا (البقرۃ:۳۰) کہ دنیا کے سب خزانے تمام بنی نوع انسان کے لئے پیدا کئے گئے ہیں نہ کہ کسی خاص شخص کے لئے.پس مزدوری ادا کردینے کے بعد بھی حق ملکیت جو مزدوروں کو حاصل تھا ادا نہیں ہوتا.اس کی ادائیگی کی یہ صورت ہو سکتی تھی کہ ان مزدوروں کو کچھ زائد رقم دے دی جائے.مگر اس سے بھی وہ حق ادا نہیں ہوسکتا تھا.کیونکہ اس طرح ان چند مزدوروں کو تو ان کا حق ادا ہو جاتا مگر باقی دنیا جو اس میں حصہ دار تھی اس کا حق ادا ہونے سے رہ جاتا.پس اسلام نے یہ حکم دیا کہ اس قسم کی کمائی میں سے کچھ حصہ حکومت کو اداکیا جائے تاکہ وہ اسے تمام لوگوں میں مشترک طور پر خرچ کرے.
Page 264
اسی طرح زمیندار جو زمین میں سے اپنی روزی پیدا کرتا ہے گو اپنی محنت کا پھل کھاتا ہے مگر وہ اس زمین سے بھی تو فائدہ اٹھاتا ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لئے بنائی گئی تھی.پس اس کی آمد میں سے بھی ایک حصہ حکومت کو قرآن کریم دلواتا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے اسے خرچ کیا جائے.اس قانون کے مطابق مزارع عشر دیتا ہے اور پھر جو مالک ہے جب اس کے پاس روپیہ جمع ہوتا ہے وہ بھی اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے.اسی طرح تجارت کرنے والا بظاہر اپنے مال سے تجارت کرتا ہے.لیکن اس کی تجارت کا مدار ملکی امن پر ہے.اور اس امن کے قیام میں ملک کے ہر شخص کا حصہ ہے.پس اس حصہ کو دلانے کے لئے کمائے ہوئے مال پر اسلام نے زکوٰۃ مقرر کر دی تاکہ کمائے ہوئے مال دوسرے لوگوں کے حصہ سے پاک ہوتے رہیں.دوسری غرض تُزَكِّيْهِمْ کے ماتحت (جس کے معنے بڑھانے اور ترقی دینے کے ہیں)یہ قرار دی گئی ہے کہ اس کے ذریعہ افراد اور ملک و قوم کی ترقی کا راستہ کھولا جائے.اس آیت میں تُطَهِّرُهُمْ کے بعد تُزَكِّيْهِمْ کا لفظ استعمال ہوا ہے.پس اس کے وہ معنے لینے پڑیں گے جو ہوں تو لغت کے مطابق لیکن تُطَھِّرُ سے مختلف ہوں تاکہ قرآن کریم کی فصاحت قائم رہے.سو جب ہم لغت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تزکیہ کے معنے علاوہ تطہیر کے ترقی دینے کے بھی ہوتے ہیں.پس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ اموال زکوٰۃ لے کر تم دلوں کی صفائی کرو اور ان کے اموال میں جو دوسروں کا حق ہے اس سے ان کے اموال کو پاک کرو.اور قوم اور ملک کی ترقی کے سامان بہم پہنچاؤ.گویا زکوٰۃ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی کا بھی ایک ذریعہ ہے.پھر قرآن کریم نے زکوٰۃ کے مصارف بھی خود بیان کر دیئے تاکہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ کس طرح زکوٰۃ کے اموال کے ذریعہ اہم قومی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے.اگر یہ اموال ان ضروریات کے لئے خرچ نہ کئے جاتے تو قوم بے دست و پا ہو کر رہ جاتی.فرمایا.اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ١ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ١ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ( التوبۃ:۶۰) یعنی زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی مندرجہ ذیل آٹھ مدّات ہیں:.۱.فقراء ۲.مساکین
Page 265
۳.زکوٰۃ کے کام پر مامور عملہ ۴.مولفۃ القلوب.یعنی جن لوگوں کی تالیف قلب مدّ ِنظر ہو.۵.فی الرقاب.یعنی جو غلام ہوں یا مصائب میں پھنسے ہوئے ہوں ان کی گلو خلاصی کرانے میں.۶.غارمین.یعنی وہ لوگ جو اپنے کسی قصور کے بغیر مالی ابتلاء میں پھنس گئے ہوں.۷.فی سبیل اللہ.یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے یا اس کی رضا کے کاموں میں.۸.ابن السبیل.یعنی مسافر.زکوٰۃ کا پہلا مصرف فقراء ہیں.یعنی وہ لوگ جو کلی طور پر یاجزوی طورپر اپنا گذارہ چلانے کے لئے دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں مثلاً اپاہج ہیں، معذور ہیں، یتامیٰ و بیوگان ہیں، ایسے تمام لوگوں کی ذمہ داری قوم پر ہوتی ہے.اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو قوم ذلیل ہو جاتی ہے.پس اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا جس سے دائمی طور پر قابلِ امداد لوگوں کی امداد ہوتی رہے اور قوم اور ملک میں ضعف پیدا نہ ہو.قرآنی آیت میں فقراء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے.مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ ہر حالت میں اس کو تمام دوسرے اخراجات پر ترجیح دی جائے گی.بلکہ اس کے صرف یہ معنے ہیں کہ عام حالات میں اس کو ترجیح دی جائے گی.ورنہ ایسے حالات بھی آسکتے ہیں جبکہ حکومت کو خود اپنی ذات میں خطرہ ہو.ایسے وقت میں افراد خواہ کتنے ہی غریب ہوں.انہیں ملت کے لئے قربانی کی دعوت دی جائے گی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے غریبوں اور امیروں سب کو بلاتے تھے اور انہیں دیا کچھ نہیں جاتا تھا.پس معلوم ہوا کہ اگر قوم و ملک کی آزادی خطرے میں ہو تو اس وقت غرباء کو بھی قربانی کے لئے بلایا جاسکتا ہے.پس یہ ترتیب جو قرآنی آیت میں فقراء کو نمبر اوّل پر رکھ کر قائم کی گئی ہے فرض نہیں مرجّح ہے.آیت میں فقراء کے بعد مساکین کا لفظ ہے لغت میں مسکین کے معنے بھی درحقیقت فقیر ہی کے ہیں.فرق صرف یہ ہے کہ مسکین ساکن فقیر کو کہتے ہیں.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکن فقیر کے یہ معنے کئے ہیں کہ وہ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور سوال کے ذریعہ کسی کو اپنی غربت کا پتہ نہ لگنے دے.یعنی صرف اس کے حالات سے علم ہو کہ وہ قابلِ امداد ہے.باوجود اس کے کہ فقیر اور مسکین کے الفاظ ایک ہی قسم کی غربت پر دلالت کرتے ہیں.انہیں الگ الگ بیان کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ صرف نادار لوگوں کا ہی فکرنہ کرے بلکہ
Page 266
ایسے لوگوں کی بھی جستجو کرے جو نادار ہیں لیکن اپنی ناداری لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے.اور تلاش کر کے ان کی مدد کرے.تیسری مد خرچ کی وَالْعٰمِلِیْنَ عَلَیْھَا کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے یعنی جو لوگ زکوٰۃ کا انتظام کرنے پرمقرر ہوں ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی اس سے ادا کی جائیں.درحقیقت وَالْعٰمِلِیْنَ عَلَیْھَا کے الفاظ میں وسعت ہے.ملکی فوج بھی عاملین کی ذیل میں آجاتی ہے.کیونکہ اگر فوج نہ ہوگی تو ملک کا امن برقرار نہ رہ سکے گا.نہ تجارت ہو سکے گی نہ زمینداری.اور اگر تجارت و زمینداری نہ ہو گی تو زکوٰۃ کہاں سے آئے گی.پس زکوٰۃ کے جمع ہونے میں فوج کا بھی بڑا دخل ہے.بہرحال زکوٰۃ کے نظم و نسق کے کارکن اوّل درجہ پر عاملین کی ذیل میں آتے ہیں.چوتھی مد مؤلفۃ القلوب کی بیان کی گئی ہے یعنی وہ لوگ جن کے دل ملے ہوئے ہیں.ظاہر ہے کہ ملے ہوئے دلوں کا ذکر کرنے کے یہی معنے ہو سکتے ہیں کہ ان کا ظاہر ملا ہوا نہ ہو.پس مؤلفۃ القلوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل اسلام یا اسلامی حکومت کی طرف مائل ہو چکے ہوں لیکن کفار کے ملک میں ہونے کی وجہ سے اپنے اسلام یا اپنی ہمدردی کو پوری طرح ظاہر نہ کر سکتے ہوں ان کو اسلامی ملک میں لانے یا ان کی دلی حالت کو قائم رکھنے میں مدد دینے کے لئے بھی زکوٰۃ کا روپیہ خرچ کیا جا سکتا ہے.یا ایسے لوگ جن کے دل اسلام کی صداقت کے قائل ہو چکے ہیں.لیکن اگر وہ اسلام کو ظاہر کر دیں تو غیر ممالک میں ان کی ملازمتیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور گذارے کی صورتیں ختم ہو جاتی ہیں.ان کی مدد کی جا سکتی ہے مؤلفۃ القلوب سے یہ مراد ہر گز نہیں کہ کسی کو روپیہ دے کر اسلام کی طرف مائل کیا جائے.کیونکہ اسلام روپیہ دے کر لوگوں کو مسلمان بنانے کی ہرگز اجاز ت نہیں دیتا.اس کی ذاتی خوبیاں ہی اس کے پھیلانے کے لئے کافی ہیں.پانچویں مد فی الرقاب بیان کی گئی ہے.یعنی غلاموں کے آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کا روپیہ خرچ کیا جا سکتا ہے.ابتدائے اسلام میں عرب میں غلامی کا رواج تھا اس لئے ان کے آزاد کروانے کا حکم تھا.کیونکہ اسلام بیع و شراء والی غلامی کو مطلقاً حرام کرتا ہے لیکن اس کے یہ معنے بھی ہیں کہ اگر کوئی جابر قوم ظالمانہ طور پر کسی کمزور قوم کو روند ڈالے اور ان کے ملک پر قبضہ کر لے اور ان کو غلام بنا لے تو کمزور قوم کی مدد کی جائے اور ان کو ظالموں کے ہاتھوں سے آزاد کرایا جائے.اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کا قرض ادا نہ کرسکنے کی صورت میں مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی زکوٰۃ کے مال سے گلو خلاصی کرائی جائے.
Page 267
چھٹی مد غارمین کی بیان کی گئی ہے.اس کی ذیل میں وہ لوگ آجاتے ہیں جن کو بعض اوقات ایسی رقوم ادا کرنی پڑجاتی ہیں جن کے براہ راست وہ ذمہ وار نہیں ہوتے.مثلاً کسی کی ضمانت دی اور جس کی ضمانت دی تھی وہ فوت ہو گیا یا کسی اور طرح سے غائب ہو گیا.تو ضامن کے پاس مال نہ ہوسکنے کی صورت میں اس کی امداد کی جا سکتی ہے.اسی طرح اس کی ذیل میں وہ تاجر بھی آسکتے ہیں جن کی تجارت ملک کے لئے مفید ہو.مگر کسی اتفاقی حادثہ کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے اور تجارت بند ہو جانے کا خطرہ ہو.ایسی صورت میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو روپیہ دے تاکہ وہ اپنی تجارت کو بحال کر کے ملک کو فائدہ پہنچا سکیں.ساتویں مد فی سبیل اللہ کی ہے.اس مد میں وہ تمام کام شامل ہیں جو قومی یا ملکی تنظیم، استحکام، حفاظت یا ان کی ترقی کے لئے کئے جائیں.اس میں فوجیں بھی شامل ہیں اور تعلیم بھی شامل ہے.سڑکیں، ہسپتال، اسی قسم کے وہ تمام کام جو صرف کسی فرد کے فائدہ کے لئے نہیں بلکہ تمام قوم کے فائدہ کے لئے ہوتے ہیں شامل ہیں.فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفۃ القلوب اور غارمین کے ذکر میں درحقیقت فردی امداد کا ذکر ہے.اور اس کے بعد ابن السبیل کا لفظ رکھ کر یہ بتایا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسے کام پیش آجاتے ہیں جو کسی فرد کی طرف منسوب نہیں کئے جا سکتے بلکہ قوم کی طرف یا ملک کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور اس قسم کے کاموں میں اجتماعی خرچ ہوتا ہے جو ملک اور ملت کے استحکام اور ترقی کے لئے کیا جانا ضروری ہوتا ہے.چونکہ ایسے خرچ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں اس لئے اس کی تفصیل بیان نہیں کی بلکہ ایک مجمل اورجامع لفظ رکھ دیا تاکہ ضرورت پیش آنے پر ذمہ وار لوگ اس کو خرچ کر سکیں.آٹھویں مد ابن السبیل کی ہے.ابن السبیل کے معنے مسافر کے ہیں.یعنی مسافروں کی امداد کرنا حکومت کا فرض ہے.یعنی سڑکوں کا بنانااور ان کی مرمت وغیرہ کا خیال رکھنا.مسافر خانے اور ڈاک بنگلے بنانا اپنے ملک میں سفر کرنے کے لئے معلومات اور سہولتیں بہم پہنچانا.اس کے متعلق لٹریچر شائع کرنا تاکہ غیر ملکوں کے لوگ آئیں اور اسلامی حکومت کو دیکھیں اور مسلمان غیر مسلمانوں سے واقف ہوں اور غیر مسلمان مسلمانوں سے واقف ہوں.اور سیّاحوں کے آنے کی وجہ سے ملک کی دولت بڑھے اور غیر ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم ہونے کی وجہ سے اسلامی ملک کی ساکھ دوسرے ممالک میں قائم ہو اور بین الاقوامی تعلقات بہتر ہوں.گویا یہ سب اغراض ابن السبیل کی مد میں آجاتی ہیں.مذکورہ بالا تفصیل کو پیش نظر رکھ کر دیکھیں کہ اسلام نے صرف زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا بلکہ بتایا کہ یہ حکم اپنے اندر
Page 268
گہرا فلسفہ رکھتا ہے اور یہ کہ اگر قوم صحیح طور پر اس حکم پر عمل پیرا رہے گی تو اس کے لئے بے شمار ترقی کے ذرائع کھلتے چلے جائیں گے.(۲)اسی طرح اسلام نے روزہ کا حکم دیا ہے.وہ فرماتا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ( البقرۃ:۱۸۴) یعنی اے مسلمانو تم پر روزے رکھنے فرض کئے گئے ہیں اور یہ کہ تم ایک مہینہ متواتراکٹھے روزے رکھو.اس کے بعد فرمایا کہ یہ حکم بے فائدہ نہیں.صرف اس لئے نہیں ہے کہ تم سارا دن بھوکے پیاسے رہو اور تکلیف اٹھاؤ بلکہ یہ حکم اپنے اندر بہت سی حکمتوں کو لئے ہوئے ہے جو قوم کے لئے بہت سے مفید پہلو اپنے اندر رکھتی ہیں.چنانچہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (البقرۃ:۱۸۴) کہ ان روزوں کے نتیجہ میں تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے گا.تَتَّقُوْنَ کا لفظ قرآن کریم میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے.(۱)دکھوں سے بچنے کے معنے میں (۲)گناہ سے بچنے کے معنے میں اور(۳)روحانیت کے اعلیٰ مدارج کے حاصل کرنے کے متعلق.پس اس لفظ کے ذریعہ روزہ کی تین حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیں.پہلی حکمت یہ ہے کہ انسان روزہ کے ذریعہ سے دکھوں سے بچ جاتا ہے.بظاہر یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ سے تو انسان اور بھی تکلیف اٹھاتا ہے.کیونکہ سارا دن اس کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے.مگر جب غور کیاجائے تو معلوم ہوجاتا ہے کہ روزہ درحقیقت انسان کو دو سبق سکھاتا ہے.اوّل سبق یہ کہ مال دار لوگ جو سارا سال عمدہ غذائیں کھاتے رہتے ہیں اور ان کو فاقہ کی تکلیف کا علم نہیں ہوتا.ان کو بھی معلوم ہو کہ فاقہ کیا ہوتا ہے اور وہ لوگ جو فاقوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے.گویا روزہ کے ذریعہ سے اپنے غریب بھائیوں کی حالت کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے اور ان کی ہمدردی کا جوش پیدا ہوتا ہے.اور اس کا نتیجہ قوم کی ترقی اور حفاظت ہوتا ہے.اور قوم کی حفاظت درحقیقت فرد کی حفاظت ہی ہوتی ہے.دوسرا سبق یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے سست اور غافل نہ ہو جائیں.بلکہ ان کے اندر مشقت برداشت کرنے کی عادت قائم رہے.چنانچہ روزوں کے ذریعہ ہر سال مسلمانوں کی تربیت ہوتی رہتی ہے.گویا اسلام کے اس حکم پر چلنے والے کبھی عیاشی اور غفلت میں مبتلا ہو کر ہلاک نہیں ہو سکتے.دوسرا امر کہ روزوں سے انسان گناہ سے بچتا ہے.اس کی حقیقت یہ ہے کہ گناہ درحقیقت مادی لذات کی طرف جھکنے کا نام ہے.اور یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی کام کا عادی ہو جائے تو وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا.مگر جب اس
Page 269
میں یہ طاقت ہو کہ اپنی مرضی پر اس کو چھوڑ بھی دے تو پھر وہ خواہش غلبہ نہیں پاتی.پس جب کوئی شخص روزوں میں ان تمام لذتوں کو جو اس کو بعض اوقات گناہ کی طرف کھینچتی ہیں خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور ایک مہینہ تک برابر اپنے نفس پر قابو پانے کی عادت ڈالتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان لالچوں کا مقابلہ آسانی سے کر سکتا ہے جو اسے گناہ کی طرف کھینچتے ہیں.پھر تقویٰ کے قیام میں روزوں سے اس طرح مدد ملتی ہے کہ ان دنوں میں چونکہ روزوں کے ساتھ تہجد کا بھی التزام کرنا پڑتا ہے.اس لئے دعاؤں اور عبادت کا زیادہ موقع مل جاتا ہے.نیز جب بندہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنے آرام کو چھوڑتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کی روح کو طاقت بخشتا ہے.پھر روزہ کی ایک اور حکمت اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (البقرۃ:۱۸۶) کہ تم پر روزہ اس لئے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرو.اس وجہ سے کہ اس نے تم کو سچا راستہ دکھایا ہے اور تاکہ تم میں شکر کرنے کا مادہ پیداہو.یعنی ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سارا دن کھانے پینے کے مشاغل سے فارغ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے گا.دوسرے بھوک کی تکلیف محسوس کر کے تمہارے اندر شکر گذاری کا مادہ پیدا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سال بھر بھوکے رہنے کی تکلیف سے بچائے رکھا ہے.(۳)اسی طرح حج ہے.اس عبادت کی اغراض بھی روزے سے ملتی ہیں.یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے وطن چھوڑنے کی عادت ڈالنی اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے الگ ہو نے کا خوگر ہونا اور عالمی و بین الاقوامی اخوت کے احساس کو پیدا کرنا اور مضبوط کرنا.علاوہ ازیں قرآن کریم نے اس کی یہ حکمت بھی بتائی ہے کہ اس عبادت سے شعائر اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور ان کی یاد تازہ رہتی ہے.حج دراصل اس واقعہ کی یاد تازہ کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ دینے کے سبب سے پیش آیا.اور دوسرے خانہ کعبہ کی نسبت قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ سب سے پہلا گھر ہے جو خدائے واحد کی عبادت کے لئے بنایا گیا.پس حج میں جا کر انسان کے سامنے وہ نقشہ کھنچ جاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کے لئے قربانی کرنے والے بچائے جاتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور حج کرنے والے کے دل میں خدا کا جلال اور اس کی ذات کا یقین بڑھتا ہے.دوسرے وہ اپنے آپ کو اس گھرمیں دیکھ کر جو ابتدائے دنیا سے خدا تعالیٰ کی یاد کے لئے بنایا گیا
Page 270
ہے ایک عجیب روحانی تعلق ان لوگوں سے پاتا ہے جو ہزاروں سال سے اس روحانی سلک میں پروئے چلے آتے ہیں جس میں یہ شخص پرویا ہوا ہے.یعنی خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کی محبت کا رشتہ جو سب کو باندھے ہوئے ہے خواہ پرانے ہوں یا نئے.غرض اسلام نے عبادات کا صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ ان کی حکمت بھی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ تمام عبادات انسان کے فائدہ کے لئے مقرر کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت منوانے کے لئے ان کا حکم نہیں دیا.جب یہ صورت ہے تو پھر عبادت کرنے والے کے دل میں کیوں بشاشت پیدا نہ ہوگی اور کیوں وہ خوشی سے ہر ایک حکم پر عمل نہیں کرے گا؟ قرآن مجید کے علاوہ دوسری الہامی کتب کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شریعت کو ایک چٹی کے طور پر پیش کیا ہے.وید تو بالکل پردوں تلے ہیں ان سے شریعت کا کوئی پتہ نہیں لگتا.تورات، ژند اوستاکو پڑھنے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں شریعت موجود ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شریعت اس لئے نہیں کہ اس میں انسان کا نفع ہے بلکہ اس لئے ہے کہ خدا یوں چاہتا ہے.جس کی وجہ سے شریعت کی اصل غرض جو اصلاحِ نفس ہے فوت ہو جاتی ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان میں بعض احکام ایسے بھی ہیں جو انسان کے نفع کے لئے ہیں لیکن اتفاقی طور پر کسی ایسے حکم کا نکل آنا اور بات ہے یہ صرف قرآن کریم نے ہی بتایا ہے کہ سب احکام انسان کے فائدہ کے لئے ہیں.دوسرا امر جس سے احکام کی تعمیل میں بشاشت پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ جس تعلیم کو انسان مانے اس میں رحمت کا پہلو غالب ہو.کیونکہ رحمت کا پہلو غالب ہونے کی وجہ سے اسے یہ فائدہ حاصل ہو گا کہ اگر اس کے عمل میں کوئی کمزوری رہ جائے گی تو رحمت کا پہلو اس کی تلافی کر دے گا اور یہ بات صرف اسلام میں ہی پائی جاتی ہے باقی مذاہب اس سے خالی ہیں.مثلاً ہندو تناسخ کے قائل ہیں.تناسخ کے عقیدہ کی رو سے یہ مانا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی انسان کا گناہ معاف نہیں کر سکتا اور کسی کو اس کے نیک عمل کا بدلہ اس کے نیک عمل سے زائد نہیں دے سکتا.تناسخ کے قائلین گناہوں کے مرتکب ہونے والے انسانوں کے لئے چوراسی لاکھ جونوں کے قائل ہیں.گناہ گار انسان انسانیت کے جامہ کی بجائے حیوانیت کے مختلف جاموں میں داخل ہو تا ہے اور اپنے گناہ کی سزا بھگتتا ہے.یہ عقیدہ اسی بنا پر ہے کہ ان کے نزدیک ایشور یعنی خدا کی جزا سزا میں رحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے.اگر ویدک فلاسفی پر غور کیا جائے تو کسی انسان کے لئے نجات پانا ممکن نہیں رہتا کیونکہ ویدوں کو پڑھے بغیر کوئی شخص صحیح طور پر نیکی اور بدی کا علم حاصل نہیں کر سکتا.اور بغیر علم
Page 271
حاصل کئے کوئی شخص بدی سے بچ نہیں سکتا.ویدوں کے پڑھنے کے لئے بلوغت کی عمر کے بعد کم از کم چھتیس برس کی وہ مدت ہے جسے پنڈت دیانند بانی آریہ سماج نے اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں مقرر کیا ہے.چنانچہ وہ لکھتے ہیں.’’آٹھویں سال سے آگے چھتیسویں سال تک یعنی ایک ایک وید کو معہ اس کے انگوں اور اپانگوں کے پڑھنے میں بارہ بارہ سال مل کر چھتیس اور آٹھ مل کر چوالیس خواہ اٹھارہ سال کا براہمچاریہ اور آٹھ سابق مل کر چھبیس یا نو سال یا جب تک پوری تعلیم حاصل نہ کرلے تب تک برہمچاریہ رہے.‘‘( ستیارتھ پرکاش باب سوم تیسرے سملاس کا آغاز صفحہ ۴۶) اس تعلیمی عرصہ میں وید پڑھنے والے سے جو گناہ ہوں گے آیا وہ گناہ معاف کئے جائیں گے اور کیا ایشور اپنے بھگتوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اس کا جواب پنڈت دیانند جی مصنف ستیارتھ پرکاش کے بیان کے مطابق حسب ذیل ہے : ’’سوال : ایشور اپنے بھگتوں کے پاپ معاف کرتا ہے یا نہیں؟ جواب : نہیں.کیونکہ اگر وہ پاپ معاف کرے تو اس کا انصاف جاتا رہے اور تمام انسان سخت پاپی ہو جائیں.کیونکہ درگذر کے سنتے ہی ان کو پاپ کرنے میں بے خوفی اور حوصلہ پیدا ہو جائے.مثلاً اگر راجہ گناہ معاف کر دیا کرے تو لوگ حوصلہ پا کر اور بھی بڑے بڑے پاپ کرنے لگیں.کیونکہ راجہ گناہ بخش دیا کرے گا اور ان کو بھی بھروسہ ہو جائے گا کہ ہم راجہ سے بذریعہ حرکات ہاتھ جوڑنے وغیرہ کے اپنے قصور معاف کرالیں گے.تو جو لوگ قصور نہیں کرتے وہ بھی تقصیروں سے نہ ڈر کر پاپ کرنے میں راغب ہو جائیں گے.اس لئے ایشور کا کام اعمال کا مناسب پھل دینا ہے نہ کہ معاف کرنا.‘‘ (ستیارتھ پرکاش باب۷ کیا ایشور اپنے بھگتوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے صفحہ ۱۸۷) گویا ایشور اپنے بھگتوں کے بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا.اب غور کر لیا جائے کہ انسان کے لئے مکتی حاصل کرنے کی کون سی صورت باقی رہ جاتی ہے.کیونکہ انسان سے غلطی اور گناہ کا ہو جانا بالخصوص جب کہ اسے ابھی ویدوں کا پوری طرح علم نہیں ہے قرینِ قیاس ہے.اور جب انسان حیوانی قالبوں میں جاتا ہے تو اس میں انسانی شعور باقی نہیں رہتا.جب وہ از سرِ نوانسانی جامہ میں آئے گا تو پھر اس کے لئے یہی تسلسل اور چکر جاری رہے گااور اس کے لئے کسی مرحلہ پر بھی نجات پانا ممکن نہ ہوگا.ہندو مذہب کے مطابق اگر کوئی شخص نجات پا بھی لے تب بھی اس کی وہ نجات اور مکتی دائمی نہیں ہے.بلکہ ایک عرصہ کے بعد اس انسان کو مکتی خانہ سے نکال کر پھر دنیا میں جونوں کے چکر میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے
Page 272
کہ وہ ایشور نجات پانے والی روح کا کوئی گناہ پوشیدہ طور پر رکھ لیتا ہے اور اس کو علت قرار دے کر پھر اس روح کو مکتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے.کیونکہ کسی گناہ کے لئے ہندو دھرم میں عفو کی گنجائش نہیں اور نہ کسی نیکی کے بدلہ میں زیادہ یا غیر محدود بدلہ دیا جا سکتا ہے.اس لئے ویدک دھرم میں مکتی کو بھی محدود مانا گیا ہے.یہی حال عیسائی مذہب کا ہے.عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت آدم نے گناہ کیا اور ان کے گناہ کی وجہ سے ساری نسل آدم گناہ گار قرار پائی اور ہر پیدا ہونے والا بچہ آدم زاد ہونے کی وجہ سے گناہ سے ملوث ہوتا ہے کیونکہ وہ آدم کا وارث ہے.عیسائیوں کے نزدیک ورثہ کا یہ گناہ خدا کے عفو کی چادر کے نیچے نہیں آسکتا جب تک اس کا بدلہ ادا نہ کیا جائے.عیسائی جب ساری نسل آدم کو گناہ گار مانتے ہیں تو وہ انبیاء اور مرسلین کو بھی معصوم نہیں سمجھتے.بلکہ انہیں بھی گناہ گار ٹھہراتے ہیں.جب سب نسلِ آدم گناہ گار ٹھہری اور کوئی گناہ بغیر بدلہ کے معاف نہیں ہو سکتا تو مجبوراً خدا تعالیٰ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا تا وہ بے گناہ ہونے کے باعث سب انسانوں کا گناہ اٹھا لے اور ان کی جگہ سزا بھگتے.عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی عفو اور رحمت سے بالکل خالی ہے.بلکہ اس میں صریح بے انصافی نظر آتی ہے کیونکہ گناہ گار آدم زادوں کی بجائے معصوم ابن اللہ کو سزا دینا ہرگز انصاف نہیں ہے.بہر حال کفارہ کا نظریہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ عیسائیوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عفو کے خیال معدوم ہیں.لیکن اسلامی تعلیم اس کے بالکل خلاف ہے.اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے اس کی صفات میں سے غفوریت، ودودیت اور رحیمیت بھی ہے.یعنی اگر عمل کرتے ہوئے کوئی کمزوری رہ جائے تو وہ اس کمزوری کو نظر انداز کرتے ہوئے انسان کے لئے ترقیات کے دروازے کھولتا رہتا ہے.اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسی محبت و رافت کا سلوک کرتا ہے جیسے ایک مشفق باپ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے.بچہ خواہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو.باپ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ ضائع ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے متعلق یہی چاہتا ہے کہ وہ نجات پاتے چلے جائیں خواہ ان کے اعمال میں کچھ کمزوریاں ہی رہ گئی ہوں اور درحقیقت ایسی ہی تعلیم پر عمل کرنے سے انسانی قلوب میں بشاشت قائم رہتی ہے.مثلاً اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور بالفرض نماز میں اس کی توجہ پوری طرح قائم نہیں رہتی تو اسلامی تعلیم کے نتیجہ میں وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میری نماز بے کار گئی.بلکہ وہ یہ سمجھے گا کہ اگر تھوڑی بہت خامی بھی رہ گئی ہوگی تو تھوڑی سی توجہ اور انابت سے اللہ تعالیٰ اس کو نظر انداز کر دے گا.اور اس کے لئے اپنے فضلوں کے دروازے بند نہیں کرے گا.
Page 273
اسی اصل کے ماتحت اسلام نے توبہ کے مسئلہ کو پیش کیا ہے.کہ اگر کسی وقت انسان سے کوئی کمزوری سرزد ہوجائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی سزاہی بھگتے.بلکہ اگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور آئندہ کے لئے وہ اپنی اصلاح کا اقرار کرے اور ایسی کمزوریوں سے بچنے کا تہیہ کر لے تو اس کی کمزوریوں کی بنا پر ترقیات کے جو دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ پھر کھول دیئے جاتے ہیں اور انسان نیچے کی طرف نہیں جاتا بلکہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے.اس اصل کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا۠ لِذُنُوْبِهِمْ١۪ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ١۪۫ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.اُولٰٓىِٕكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا١ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ( اٰلِ عـمران: ۱۳۶،۱۳۷) یعنی وہ لوگ جو کسی وقت خدا کے احکام کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں اور اس ذریعے سے اپنے نفسوں کا حق مار دیتے ہیں.لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں.وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں سے اور کمزوریوں سے بچا سکے.یہ جملہ معترضہ ہے.آگے فرماتا ہے وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.وہ خدا تعالیٰ سے اپنی کمزوریوں پر پردہ پوشی چاہتے ہیں اور اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کمزوریوں پر پردہ پوشی فرما کر ان کے لئے رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے.ان لوگوں کی جو اس نکتہ کو سمجھتے ہیں یہ جزا ہو گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں پر پردہ ڈال دے گا اور ان کے لئے اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرے گا اور وہ نجات پا کر خدا تعالیٰ کو پا لیں گے اور ان کو مغفرت حاصل ہو جائے گی اور رہنے کو ایسے باغا ت ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور یہ انعام عارضی نہیں ہوگا.بلکہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اور محنت کرنے والوںکا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے.دیکھو کیسی اعلیٰ اور شاندار تعلیم ہے.انسان کے لئے مایوسی کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے ہیں اور اسے یقین دلایا گیا ہے کہ وہ ہر وقت ترقی کی شاہراہ پر گامزن رہ سکتا ہے.ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اندر احساس صحیح پیدا کرے.انسان کے دل میں یہ خیال آسکتا تھا کہ ممکن ہے خدا تعالیٰ ایک دو کمزوریوں کو تو نظر انداز کردے لیکن اگر کسی انسان سے بہت سی کمزوریاں سر زد ہو چکی ہوں اور اس نے اپنے خیال میں نجات کا دروازہ اپنے لئے بند کر لیا ہو تو اس کا
Page 274
کیا ہو گا؟ ایسے لوگوں کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا١ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (الزّمر:۵۴) اے ہمارے رسول ! ان لوگوں کو اچھی طرح کھول کر سنا دے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزوریوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور وہ نکل نہیں سکتے اور اب ان کے لئے نجات کا دروازہ بند ہو چکا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو.اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ خواہ کس قدر کمزوریاں کیوں نہ سرزد ہو چکی ہوں.ان سب سے درگذر کر سکتا ہے ان سب کو معاف کر سکتا ہے اور نجات کا دروازہ کھول سکتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ انسانی اندازوں سے بڑھ کر پردہ پوشی کرنے والا اور بے حد و حساب رحمت کرنے والا ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے اس کا اندازہ کرنا ناممکن ہے.پس اللہ تعالیٰ نے ہر مقام کے لوگوں کے لئے اپنی رحمت کو پیش کیا ہے اور مایوس ہونے سے روکا ہے.اور فرمایا ہے کہ ہر شخص خدا کی رحمت کو حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اصل چیز اس کی صفات میں سے رحمت ہی ہے.احادیث میں آتا ہے اِنَّ نَبِیَّ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ فِیْمَنْ کَانَ قَبْلَکُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَۃً وَ تِسْعِیْنَ نَفْسًا فَسَئَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَھْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰی رَاھِبٍ فَاَتَاہُ فَقَالَ اِنَّہُ قَتَلَ تِسْعَۃً وَ تِسْعِیْنَ نَفْسًا فَھَلْ لَّہُ مِنْ تَوْبَۃٍ فَقَالَ لَا.فَقَتَلَہُ فَکَمَّلَ بِہٖ مِائَۃً ثُمَّ سَئَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَھْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰی رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ اِنَّہُ قَتَلَ مِائَۃَ نَفْسٍ فَھَلْ لَّہُ مِنْ تَوْبَۃٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ یَّحُوْلُ بَیْنَہُ وَ بَیْنَ التَّوْبَۃِ.اِنْطَلِقْ اِلٰی اَرْضٍ کَذَا وَکَذَافَاِنَّ بِھَااُنَاسًایَّعْبُدُوْنَ اللّٰہَ تَعَالٰی فَاعْبُدِ اللہَ مَعَھُمْ وَلَا تَرْجِعْ اِلٰی اَرْضِکَ فَاِنَّـھَا اَرْضُ سُوْءٍ.فَانْطَلَقَ حَتّٰی اِذَا نَصَفَ الطَّرِیْقَ اَتٰہُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِیْہِ الْمَلٰٓـئِکَۃُ الرَّحْـمَۃِ وَمَلٰٓـئِکَۃُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلٰٓـئِکَۃُ الرَّحْـمَۃِ جَآءَ تَائِبًا مُقْبِلًا اِلَی اللہِ تَعَالٰی وَ قَالَتْ مَلٰٓـئِکَۃُ الْعَذَابِ اِنَّہُ لَمْ یَعْمَلْ خَیْرًا قَـــــطُّ.فَاَتٰـھُمْ مَّلَکٌ فِیْ صُوْرَۃِ اٰدَمِیٍّ فَـجَعَلُوْہُ بَیْنَـھُمْ فَقَالَ قِیْسُوْا مَا بَیْنَ الْاَرْضَیْنِ فَاِلٰی اَیَّتِھِمَا کَانَ اَدْنٰی فَھُوَ لَہُ فَقَاسُوْہُ فَوَجَدُوْہُ اَدْنٰی اِلَی الْاَرْضِ الَّتِیْ اَرَادَ فَقَبَضَتْہُ مَلٰٓـئِکَۃُ الرَّحْـمَۃِ(ریاض الصالـحین باب التوبۃ).وَفِیْ رِوَایَۃٍ فِی الصَّحِیْحِ فَکَانَ اِلَی الْقَرْیَۃِ الصَّالِـحِ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَـجُعِلَ مِنْ اَھْلِھَا(صحیح مسلم کتاب التوبۃ باب قبول توبۃ القاتل و ان کثر قتلہ).وَفِیْ رِوَایَۃٍ فِی الصَّحِیْحِ فَاَوْحَی اللّٰہُ تَعَالٰی اِلٰی ھٰذِہٖ اَنْ تَبَاعَدِیْ وَ اِلٰی ھَذِہٖ اَنْ تَقْرِبِیْ وَقَالَ قِیْسُوْا مَا بَیْنَـھُمَا فَوُجِدَ اِلٰی ھٰذِہٖ اَقْرَبُ بِشِبْرٍ فَغُفِر لَہُ.(صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الغار) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے زمانہ میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے قتل کئے تھے وہ توبہ
Page 275
کے لئے کسی عالم کے پاس گیا اور اس کے پاس جا کر کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی.اس شخص نے کہا کہ اگر میری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو میں تجھے بھی مار دوں گا ایک گناہ اور زیادہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا.یہ کہہ کر اس نے اس عالم کو قتل کر دیا.پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی اور ایسا عالم ہے جس سے وہ مسئلہ دریافت کر سکے.تو اسے ایک عالم شخص کا پتہ بتایا گیا.وہ اس کے پاس پہنچا اور بتایا کہ اس نے سو قتل کئے ہیں.کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا.کیوں نہیں.کون ہے جو بندہ کے اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکے.لیکن شرط یہ ہے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ.وہاں کئی خدا کے بندے مل کر عبادت کر تے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل کر عبادت کرو اور اپنے ملک میںمت لوٹو.کیونکہ وہ اچھی جگہ نہیں.یہ سن کر وہ شخص اس جگہ پہنچنے کے لئے روانہ ہو گیا.جب نصف راستہ پر پہنچا تو اس کو موت نے آلیا تب رحمت کے فرشتے بھی آگئے اور عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے.دونوں میں بحث شروع ہو گئی.دوزخ والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ شخص دوزخی ہے اسے توبہ ابھی نصیب نہیں ہوئی.اور جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا کہ راستہ میں مر گیا.تب ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے اس کو منصف بنایا.تو اس نے کہا کہ زمین کو ماپو.جس طرف سے یہ شخص توبہ کرنے کے لئے چلا تھا اگر وہ جگہ قریب ہو تو یہ دوزخی ہے اور اگر وہ جگہ جہاں یہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا قریب ہے تویہ جنتی ہے تب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ما تحت زمین کی طنابیں کھینچ دیں اور اس جگہ کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لئے جارہا تھا زیادہ قریب کر دیا.فرشتوں نے دونوں طرف کی زمین کو ماپا اور دیکھا کہ وہ زمین جس طرف یہ شخص توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا چھوٹی ہے.خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ تب اسے جنت میں لے جاؤ.اس تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.کیونکہ خدا تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے.اس کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا.اور یہ کہ اسلام بھی ایسے ہی خدا کو پیش کرتا ہے جس کی رحمت کا پہلو ہمیشہ انسان کی طرف جھکا رہتا ہے.چنانچہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو پیش کرتا ہے.فرماتا ہے رَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (الاعراف:۱۵۷) کہ میری رحمت ہر ایک چیز پر وسیع ہے.پھر فرمایا كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (الانعام:۱۳) کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے.یعنی یہ کہ اس کی رحمت کا پہلو زیادہ جھکا ہوا ہے.پھر فرمایا وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ.اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ١ؕ وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ(ھود:۱۱۹،۱۲۰) کہ اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو امتِ واحدہ بنا دیتا مگر وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے.سوائے ان کے جن پر تیرا رب رحم کرے اور اس نے ان لوگوں کو رحم کے لئے ہی پیدا کیا ہے وَ لِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ سے رحم ہی مراد ہے.ابن کثیر نے
Page 276
حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کی ہے لِلرَّحْـمَۃِ خَلَقَھُمْ وَلَمْ یَـخْلُقْھُمْ لِلْعَذَابِ کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے لئے ہی بندوں کو پیدا کیا ہے عذاب کے لئے نہیں پیدا کیا.غرض اسلام کی پیش کردہ تعلیم میں رحمت کا پہلو غالب ہے اور جس تعلیم میں یہ بات پائی جائے کبھی بھی اس پر عمل کرنے میں انقباض پیدا نہیں ہو گا.بلکہ اس کا ماننے والا ہمیشہ ہی پُر امید رہے گا اور یہ سمجھ کر عمل کرے گا کہ اگر اس کے اعمال میں کوئی کمزوری رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تھام لے گی.لیکن دوسرے مذاہب کی تعلیم میں ایسی بات نہیں پائی جاتی.اس لئے ان کے احکام پر عمل کرتے ہوئے بشاشتِ قلب پیدا نہیں ہو سکتی.تیسری بات جس سے احکام کی تعمیل میں بشاشت پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تعمیل احکام میں ایسے فوائد موجود ہوں جو جزائے اعمال کو اعمال کی نسبت سے زیادہ بتاتے ہوں اور یہ بات بھی صرف اسلامی تعلیم میں پائی جاتی ہے.دوسرے مذاہب اس سے خالی ہیں.اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے اس کی صفات میں سے ایک صفت رحیمیت کی ہے.او ررحیمیت کے معنے یہ ہیں کہ تھوڑا ساکام بندہ کرتا ہے اور غیر منتہی نتیجہ خدا پیدا کرتا ہے.مثلاً انسان روٹی کھاتا ہے.روٹی کھانے کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر جاتا ہے بلکہ اس کے نتیجہ میں خون پیدا ہوتا ہے جو مہینوں اور سالوں انسانی جسم میں کام کرتا ہے.اسی خون سے اس کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، اس کی نظر کو طاقت ملتی ہے، اس کے ذہن کو طاقت ملتی ہے، اس کے کانوں کو طاقت ملتی ہے جو مہینوں اور سالوں اس کے کام آتی ہے.اور پھر و ہ کام مہینوں اور سالوں تک مزید نتائج پیدا کرتے ہیں.پھر اسی میں سے نطفہ پیدا ہوتاہے جس سے اس کی نسل پیدا ہوتی ہے پھر اسی نسل سے اگلی نسل اور اگلی نسل سے اور اگلی نسل پیدا ہوتی ہے.گویا ایک فعل تواتر سے نتائج پیدا کرتا ہے.یہ رحیمیت ہے.اگر دنیا میں صرف یہی سلسلہ ہوتا کہ جب کوئی شخص کام کرتا تو اسی وقت اس کا ایک نتیجہ پیدا ہو جاتا تو ہم اس کو بدلہ تو کہہ سکتے تھے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے تو اپنی اجرت لے لیتا ہے مگر ہم اسے رحیمیت نہیں کہہ سکتے تھے.رحیمیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پنشن ہوتی ہے.لوگ ملازمت کرتے ہیںتو انہیں اس کا بھی ایک بدلہ مل رہا ہوتا ہے.مگر اس کے ساتھ ہی ان کے کھاتےمیں یہ بھی لکھا جا تا ہے کہ آئندہ اس کام کا متواتر نتیجہ پیدا ہو گا.یہ چیز ہے جو رحیمیت کے مشابہ ہے یعنی کام کا بدلہ نقد ہی نہیں ملا بلکہ آئندہ کے لئے اور نیک نتائج کی بنیاد بھی ساتھ ہی رکھ دی گئی.غرض رحیمیت میں تھوڑا سا کام بندہ کرتا ہے اورغیر منتہی نتیجہ خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے.اور اگر انسان کو یہ نظر آجائے کہ مجھے میرے اعمال کی جو جزا ملنے والی ہے وہ میرے اعمال کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہو گی تو انسان طبعی
Page 277
طور پر چاہے گا کہ وہ خدا کے ارشاد کے مطابق اعمال کوبجالائے.تاکہ اسے اس کے اعمال کا غیر محدود بدلہ ملتا جائے اور جب انسان کو اچھی طرح یہ سمجھ آجاتا ہے اور اس پر یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جزا دیتا ہے تو متواتر دیتا چلا جاتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک خوشی اور لذت کی لہر محسوس کرتا اور نیک اعمال کے بجا لانے میں بہت زیادہ جدوجہد کرتا ہے تاکہ وہ خدا تعالیٰ کی غیر محدود جزا سے حصہ لے سکے.قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ مومنوں کے اعمال کا بدلہ ان کے اعمال سے بہت بڑھ کر ہو گا.چنانچہ فرمایا :.اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُواالصّٰلِحٰتِ فَلَھُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ( التّین:۷ ) کہ وہ لوگ جو مومن ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو نہ کٹنے والا انعام ملے گا.پھر فرمایا:.مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا١ۚ وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (الانعام: ۱۶۱) یعنی جو شخص نیکی کرے گا اسے اس نیکی سے دس گنے زیادہ بدلہ ملے گا اورجو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہو گی.نیکی کا کم بدلہ دے کر اس کا حق نہیں مارا جائے گا اور نہ بدی کا بدلہ زیادہ دے کر اس پر ظلم کیا جائے گا.ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک نیک عمل کے بدلہ میں دس گنا اجر ملے گا.بہر حال عمل سے بڑھ کر جزا ہو گی.پھر فرمایا :.مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ١ؕ وَ اللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ١ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (البقرۃ:۲۶۲) یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں یعنی قومی اور ملی مفاد کے لئے اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے اور وہ سات بالیاں اگائے اور ہر ایک بالی میں سَو دانہ ہو اور اللہ تعالیٰ جس کے مال کو جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حالات کو جاننے والا ہے.ان آیات میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اموال خرچ کرنے والے کو سات سو گنے بلکہ اس سے بھی زیادہ بدلہ ملے گا اور وہ انسان کی قربانی کو دیکھ کر اسے نوازے گا اور ان حالات کو جن حالات میں اس نے قربانی کی ہے مدّ ِنظر رکھے گا.بہرحال جس شخص کو یہ علم ہو کہ اس کے عمل کا سات سو گنا اجر مل سکتا ہے وہ کیوں بشاشت قلبی سے اعمال کو بجا نہ
Page 278
لائے گا.چوتھی چیز جس سے احکام کی تعمیل میں بشاشت قلبی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خود سمجھ آجائے کہ شریعت کے احکام اس کے حق میں مفید ہیں اور یہ کہ ان پر چل کر اسے اس کا مقصود مل سکتا ہے.پس جب اس کو یہ سمجھ آجائے گی تو وہ شریعت پر خوشی سے عمل کرے گا اور اسے چٹی نہیں سمجھے گا.یہ بات بھی صرف اسلام کی پیش کردہ تعلیم میں ہی ہے کہ نہ صرف اس پر چل کر خدا تعالیٰ بندہ سے راضی ہو جاتا ہے بلکہ ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے اس عمل کرنے والے کی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی قوم کو بھی.مثلاً نماز ہے.نماز پڑھنے سے صرف یہی نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی لقاء ہوتی ہے.بلکہ انسان کو ذاتی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ(العنکبوت:۴۶) کہ حقیقی نماز انسان کو بدیوں اور برائیوں سے روکتی ہے.پس جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو ذاتی طور پر یہ فائدہ پہنچے گاکہ وہ کئی قسم کی بدیوں سے بچ جائے گا.جس سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں رہ سکتے.گویا نماز پڑھنے والا ایک محفوظ قلعہ میں داخل ہو جائے گا جس کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا.پھر نما ز سے کئی قومی فوائد حاصل ہوتے ہیں.یہ امر ہر وقت سامنے رہتا ہے کہ ہم نے اپنے شیرازہ کو قائم رکھنا ہے.ہمارا ہر وقت ایک واجب الاطاعت امام ہونا چاہیے.جس کے ہاتھ پر قوم جمع رہ کر اسلامی جھنڈے کو بلند رکھ سکے.اسی طرح مسجدمیں جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوجاتی ہے.گویا وہ مقصد جس کو ہر عقلمند قوم چاہتی ہے مسلمانوں کو زائد طور پر حاصل ہو جاتا ہے.اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ ہیں.ان سے صرف روزہ رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے کا ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کسی قوم کی تنظیم اور اس کی مضبوطی کے لئے جن باتوں کی ضرور ت ہو سکتی ہے مسلمانوں کو مفت میں حاصل ہوجاتی ہیں.اسی طرح اسلامی عبادات میں سے ایک حج بھی ہے اس میں ذاتی فوائد کے علاوہ سیاسی فائدے بھی ہیں کہ ذی اثر لوگوں میں سے ایک جماعت ہر سال جمع ہو کر تمام عالم کے مسلمانوں کی حالت سے واقف ہوتی رہتی ہے اور اخوت و محبت ترقی کرتی ہے.اور ایک دوسرے کی مشکلات سے آگاہ ہونے اور آپس کے تعاون کے حاصل کرنے اور ایک دوسرے کی خوبیاں اخذ کرنے کا موقع ملتا ہے اور اگر تمام عالم اسلامی کے مسلمان مل کر باہمی فائدے کے
Page 279
لئے کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.پس وہ تمام باتیں جو احکام کی تعمیل میں بشاشت قلبی اور حقیقی اطاعت کی روح پیدا کر سکتی ہیں صرف اسلام کی پیش کردہ تعلیم میں ہیں اور کسی مذہب کے احکام میں نہیں.اس لئے شرک یا دوسرے مذاہب کی موجودہ حالت میں فرمانبرداری تو ہو سکتی ہے.مگر اطاعت نہیں ہو سکتی جس چیز کو غیر مذاہب کے ماننے والے اطاعت کا نام دیتے ہیں وہ درحقیقت پیروی کرنا ہے جس کا نام غلطی سے اطاعت رکھ لیا گیا ہے.مثلاً مشرکین کو لے لیں (اس سورۃ میں صرف مشرکین کا ذکر نہیں بلکہ سب کفار کا ذکر ہے)مشرکین کے مذہب کی بنیاد (۱)رسم و رواج پر (۲)اوہام پر اور (۳)دائمی زندگی کے انکار پر ہے.اور شرح صدر اور احکام کی تعمیل کا شوق ان امور کی موجودگی میں نا ممکن ہے.جو شخص صرف اس لئے کوئی کام کرتا ہے کہ اس کے باپ دادا ایسا کرتے تھے وہ ایک قسم کے جبر کے ما تحت ایسا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو لوگ نا خلف سمجھیں گے.قوم میں ناک کٹ جائے گی.پس رسم و رواج کی اطاعت بشاشت سے نہیں ہوتی.اسی طرح جو شخص محض وہم کی بنا پر کسی امر کو سر انجام دیتا ہے وہ بھی بشاشت سے اس کو بجا نہیں لاتا.کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ کل کو کوئی اور وہم اسے اس کام کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر دے.چنانچہ مشرکین روزانہ اپنے طریق کو بدلتے ہیں.کوئی کسی بت کو مانتا ہے.کوئی کسی کو.کوئی کسی طریق کو اختیار کرتا ہے کوئی کسی طریق کو.تیسرے.دائمی زندگی کے انکار کی وجہ سے بھی اعمال محض ایک محدود دائرہ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور عمل میں وہ قربانی اور بشاشت نظر نہیں آتی جو ایک دائمی زندگی پر ایمان لانے والے کو نصیب ہو سکتی ہے.ان تمام باتوں کے خلاف اسلام رسم و رواج کا سخت مخالف ہے.کیونکہ بہت سی رسوم بھی بدی کا ایک راستہ بن جاتی ہیں.بہت سی بدیاں انسان اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ رسوم میں جکڑا ہوا ہوتا ہے.مثلاً اس کے پاس روپیہ کافی نہیں ہوتا اور ملک کی رسم چاہتی ہے کہ خاص قسم کا لباس پہنے.وہ اس رسم کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے ناجائز ذرائع سے روپیہ کما تا ہے.اس لئے اسلام رسموں سے منع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ ایک بوجھ ہیں جن کو قومی خوف کی وجہ سے انسان اٹھاتا ہے ورنہ وہ بوجھ طاقت سے بڑھ کر ہوتے ہیں.کیونکہ ان میں غریب اور امیر، مقروض اور آزاد کا لحاظ نہیں رکھا جاتا.اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی خیالی عزت کی حفاظت اور اپنے ہم عصر لوگوں میں ذلیل ہونے سے بچنے کی غرض سے گناہ اور بدی میں مبتلا ہوں.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک غرض یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ تا آپ کے
Page 280
ذریعہ لوگوں کو رسوم کے پھندے سے نکالا جائے.چنانچہ فرمایا اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ١ٞيَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓىِٕثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف:۱۵۸) یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر ان لوگوں کو ملے گی جو کامل طور پر اس موعود رسول کی اطاعت کریں گے جس کی بعثت کی بشارات کو و ہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں.وہ رسول وقت پر مبعوث ہو کر انہیں نیک کاموں کی تلقین کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتا ہے اور وہ ان سے سخت حکموں کے بوجھوں کو اور رسومات کے پھندوں کو جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے دور کرتا ہے.چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ایک غرض رسم و رواج کو مٹانا تھا.اس لئے اسلام نے صرف رسوم کی مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان کو مختلف دلائل کے ذریعہ سے جڑ سے اکھیڑنے کی پوری کوشش کی ہے.چنانچہ اس نقطۂ نظر کے ما تحت رسم و رواج کے پیچھے چلنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا.وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا١ؕ اَوَ لَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ (المآئدۃ:۱۰۵) یعنی جب لوگوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اسی شریعت کی پیروی کروجو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے.تو اس کے جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن رسوم و عادات پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا وہی طریق ہمارے لئے کافی ہے.کیا اپنے باپ دادا کی تقلید کا دعویٰ کرنے والے یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان رسوم کے ترویج دینے والے نہ تو کوئی ذاتی علم رکھتے ہوں جس کی بنا پر انہوں نے ان رسوم کو چلایا اور نہ انہیں خدا کی طرف سے کوئی ہدایت ملی ہو کہ وہ ان رسوم کو رائج کریں.بلکہ ان کی جاری کردہ رسوم سراسر جہالت پر مبنی ہوں تو کیا یہ لوگ پھر بھی لکیر کے فقیر بنے رہیں گے.گویا اسلام رسم و رواج کی تقلید کرنے کو جہالت قرار دیتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ ہر کام کی بنیاد واقعات، حقائق اور بیّنات و شواہد پر ہونی چاہیے.جیسے فرمایا اے ہمارے رسول اعلان کر دو کہ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ (یوسف:۱۰۹) میرے اور میرے متبعین کے عقائد کی بنیاد رسم و رواج پر نہیں بلکہ ہماری بنیاد حقائق و شواہد اور بیّنات پر ہے.کیونکہ کامیابی رسم و رواج پر چل کر نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمدہ ہدایت ہی کامیابیوں کے راستے کھولتی ہے.پس اسلام رسم و رواج کو مٹاتا اور اس کی سخت مخالفت کرتا ہے اور رسم و رواج پر چلنے والوں اور اس کی ترویج کرنے والوں کو جاہل قرار دیتا ہے اور اس کے مقابل پر خدائی ہدایت پر چلنے کی دعوت دیتا ہے.کیونکہ حقیقی اطاعت کا مادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی
Page 281
ہدایت سے ہی پیدا ہو سکتا ہے اور رسم و رواج کی پیروی جبر و اکراہ سے ہوتی ہے نہ کہ بشاشتِ قلب سے.(۲)پھر ایک حقیقی مسلم مشرکوں کے معبودوں کی اطاعت کر کیسے سکتا ہے جبکہ ان کی طرف منسوب ہونے والے خیالات وہموں کامجموعہ ہیں.بتوں کے متعلق یہ خیالات کہ اگر ان کی عبادت نہ کی گئی تو نقصان پہنچائیں گے سوائے اوہام کے اور کیا قرار دیئے جا سکتے ہیںاور ایسے ہی اوہام کی بنا پر لوگ ان بتوں کے سامنے اپنی اولاد کی قربانی دے دیتے ہیں.حالانکہ بت ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہوتے ہیں.پر وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں.حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ تھے اور ایک عرصہ تک مہاراجہ کشمیر کے طبیب خاص بھی رہے ان کو ایک دن مہاراجہ کشمیر نے کہا کہ آپ اور کچھ نہیں کرتے تو کالی دیوی کی پوجا تو ضرور کر لیا کریں کیونکہ وہ بڑی سخت ہے.حضرت خلیفہ اوّل فرمانے لگے.مہاراج یہ دیوی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتی.تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مہاراجہ خود ہی کہنے لگا کہ ہاں مولوی صاحب بات میری سمجھ میں آگئی جو شخص میری حکومت میں نہیں رہتا میں اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا.اسی طرح چونکہ آپ کالی دیوی کی حکومت تسلیم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو اس کی حکومت سے باہر قرار دیتے ہیں اس لئے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی.غرض بتوں کی طرف منسوب ہونے والی باتیں محض توہم پرستی کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ایک غور و فکر کرنے والا انسان توہم پرستی کا شکار نہیں بن سکتا.چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر ہند ہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور مسلمانوں کی سخت مخالف تھی.حتی کہ اس نے اپنی مخالفت کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ کچا چبا یا تھا(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام غزوۃ احد).وہ عورتوں کے جھنڈ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور بغیر اپنا نام بتانے کے بیعت کر لی.چونکہ وہ ایک دلیر عورت تھی اس لئے بیعت کے وقت خاموش نہ رہ سکی.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ اے عورتو! اقرار کرو کہ ہم شرک نہ کریں گی تو ہندہ بے ساختہ بول اٹھی کہ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ بتوں کی کچھ طاقت نہیں.آپ کو خدا نے کامیابی و کامرانی دی اور ہم ذلیل ہوئے تو اب اس کے بعد ہم کس طرح شرک کر سکتی ہیں.(السیرۃ الـحلبیۃ ذکر فتح مکۃ ) پس بتوں کی طرف منسوب ہونے والی تعلیم محض وہم ہوتی ہے.قرآن کریم میں سور ہ ٔ انعام میں تفصیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشرکوں میں بعض باتیں محض اوہام کی بنا پر رائج تھیں.مثلاً یہ کہ اس اس قسم کے جانورفلاں قسم کے لوگ کھا سکتے ہیں اور فلاں قسم کے لوگ ان جانوروں کو نہیں
Page 282
کھا سکتے.جن لوگوں کو منع کیا گیا ہے اگر وہ ان جانوروں کو کھائیں گے تو ان کو نقصان پہنچے گا.اسی طرح بعض سواری کے جانوروں کو وہ محض اوہام کی بنا پر چھوڑ دیتے اور کہتے تھے کہ فلاں فلاں جانوروں پر سواری نہیں کرنی چاہیے.اور جن جانوروں کو مشرک لو گ بتوں کا چڑھاوا قرار دے کر ان سے کام لینا حرام قرار دے دیتے تھے.ان میں سے بعض دفعہ نر کو اور بعض دفعہ مادہ کو اور بعض دفعہ جو بچہ ان کے پیٹوں میں ہوتا اسے مردوں کے لئے حلال اور عورتوں کے لئے حرام قرار دے دیتے اور یہ سب کچھ وہم کا نتیجہ تھا اور کچھ نہیں.کیونکہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل نہ تھی.قرآن کریم ان کی رسوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے :.ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ١ۚ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ١ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ۠ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ١ؕ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.وَ مِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ١ؕ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ۠ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ١ؕ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا١ۚ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (الانعام:۱۴۴،۱۴۵) یعنی اللہ تعالیٰ نے آٹھ جوڑوں کو پیدا کیا ہے.دُنبہ میں سے دو کو اور بکرے میں سے دو کو (یعنی نر و مادہ کو)تُو ان سے کہہ کہ کیا اس نے دونروں کو حرام کیا ہے یا دو مادینوں کو یا اس چیز کو جو مادینوں کے رحموں میں پائی جاتی ہے.اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم کی بنا پر یہ بات بتاؤ.اور اس نے اونٹ میں سے دو کو اور گائے میں سے دو کو پیدا کیا ہے (یعنی نر و مادہ کو)تُو ان سے کہہ کہ کیا اس نے دو نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادینوں کو یا اس چیز کو جو مادینوں کے رحموں میں پائی جاتی ہے.کیا تم اس وقت جب تمہیں اللہ نے اس امر کا حکم دیا تھا موجود تھے؟ اگر نہیں تو پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ پر اس لئے جھوٹ باندھے کہ لوگوں کو علمی دلیل کے بغیر گمراہ کر دے.اللہ ظالم لوگوں کو یقیناً راہ نہیں دکھاتا.ان آیات میں قرآن کریم نے مشرکوں کی جاری کردہ رسوم کو جو بتوں کے نام پر کی جاتی تھیں صرف وہموں کا مجموعہ قرار دیا ہے.حقیقت یہ ہے کہ یہ بات صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہیں تھی کہ وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں توہم پرستی تھی بلکہ اور ملکوں میں اب بھی ایسی رسومات پائی جاتی ہیں جو محض وہم کی بنا پر ہوتی ہیں.
Page 283
قرآن کریم نے ایسی تمام باتوں کی سختی سے مخالفت کی ہے.کیونکہ اس کا پیش کردہ اصل یہ ہے کہ ہر بات حکمت کی بنا پر ہونی چاہیے تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے دل میں بشاشت پیدا ہو.اور اوہام کی باتوں کی اطاعت اکراہ اور جبر سے ہوتی ہے نہ کہ بشاشت سے.(۳) پھر مشرکین کے عقائد کے خلاف اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہماری زندگی صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ مرنے کے بعد ایک غیر منقطع زندگی ملے گی.اور موت درحقیقت اس دنیا سے اگلی دنیا میں نقل مکانی کا نام ہے اور یہ دنیا مزرعۃ الآخرۃ ہے یعنی جیسے جیسے اعمال کئے ہوں گے ویسا ہی بدلہ ہمیں ملے گا.جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے.بہرحال وہ شخص جو حیاۃ بعد الموت کا قائل نہیں اس کے اعمال محض محدود دائرہ کے لئے ہوں گے اور ان کے کرنے سے اس میں بشاشت پیدا نہ ہوگی.لیکن ایک مومن جو حیاۃ الآخرۃ کو مانتا ہے اس کے اعمال قربانی پر منحصر ہوں گے اور اس کے اندر بشاشت ہو گی.پس حیاۃ بعد الموت کا عقیدہ مومن کو بشاشت سے اعمال بجا لانے کے لئے ایک خاص تقویت بخشتا ہے.اسی لئے قرآن کریم نے اس عقیدہ کو بار بار پیش کیا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :.وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ(التوبۃ:۷۲) یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو ایسی جنات عطا کی جائیں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہتے چلے جائیں گے اور بہترین رہنے کی جگہیں انہیں دی جائیں گی اور یہ باغات اور نہریں ہمیشہ کے لئے ہوں گی نہ کہ عارضی.پس اسلام اس نظریہ کو پیش کرتا ہے کہ صرف اس دنیا کی زندگی نہیں بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ملے گی اور اصل زندگی وہی ہے اور یہ کہ اس کے لئے اس دنیامیں اعمال بجا لانے چاہئیں.چنانچہ فرمایا :.وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ١ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (العنکبوت:۶۵) کہ یہ دنیا تو عارضی ہے اور اصل زندگی تو بعد از موت حاصل ہو گی.کاش لوگ اس بات کو جان لیں.ان تمام امور کے علاوہ اسلام ایسے خدا کو پیش کرتا ہے جو سراپا محبت ہے.وہ اپنے عبادت گذاروں کی دعائیں سنتا اور ان کی مشکلات کے وقت ان کے مصائب کو دور کرتا ہے اور اپنے محبت بھرے کلام سے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے.جیسے فرمایااَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ (النمل:۶۳) کہ اللہ کے سوا وہ کون سی ہستی ہے جو
Page 284
لاچار کی دعا کو سنتی ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتی ہے یعنی ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں.صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس میں یہ وصف پایا جاتا ہے.پھر فرمایا :.اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ١ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ (البقرۃ:۱۸۷) یعنی میں اپنے بندوں کے قریب ہوں اور ان کی پکار کو سنتا ہوں.پس جب عبادت کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ میرے معبود میں یہ وصف پایا جاتا ہے کہ وہ میری دعاؤں کو سنے گا اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ میری ہر قسم کی مشکلات کو دور کرے.تو وہ احکام عبادت خوشی سے بجا لائے گا اور دوڑتے ہوئے اپنے معبود کے آستانہ پر گرے گا.اس کے مقابل پر مشرک جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے عبادت گذاروں کی نہ تو دعائیں سنتے ہیں اور نہ ان سے بولتے ہیں اور نہ ان کی مشکلات میں ان کے کام آتے ہیں.اس قسم کی ہستیوں کو ماننا یا نہ ماننا برابر ہوتا ہے چہ جائیکہ ان کی عبادت کی جائے.قرآن کریم بھی بتوں کے معبود نہ بن سکنے کی یہی دلیل بیان فرماتا ہے.چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اور سامری نے ان کی قوم کے سامنے زیورات سے بنا کر بچھڑا معبود کے طور پر پیش کیا اور قوم کا کچھ حصہ گمراہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ واپس تشریف لائے اور اس بچھڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا.اس بچھڑ ے کے معبود نہ بن سکنے اور اس کو معبود سمجھنے والوں پر ان کی غلطی واضح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :.اَفَلَا یَرَوْنَ اَلَّا یَرْجِعُ اِلَیْھِمْ قَوْلًاوَّ لَا یَمْلِکُ لَھُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا (طٰہٰ:۹۰) یعنی کیا یہ بچھڑے کے عبادت گذار نہیں سمجھتے کہ معبود تو اس ہستی کو بنانا چاہیے جو دعائیں سنے.تکالیف کو دور کرے اور اپنی محبت کا اظہار کرے.لیکن یہ بچھڑا تو ان صفات کا مالک نہیں.نہ وہ دعا سن کر جواب دیتا ہے اور نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی نقصان سے بچا سکتا ہے.پس ایسی کمزور چیز کو معبود بنانا سراسر غلطی ہے.پس اسلام نے خدا تعالیٰ کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ ہر مومن کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ دوڑتا ہوا اس کے آستانے پر آگرتا ہے اور احکام کے بجا لانے میں ایک لذت محسوس کرتا ہے.جبکہ کافر اپنے معبودوں کی عبادت کو ایک بوجھ سمجھتا ہے اور احکام کو ایک چٹی تصور کرتا ہے.اسلام کے مقابلہ میں عیسائیت کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے احکام بے حکمت قرار پاتے ہیں.مسیحیت کی بنیاد شریعت کے لعنت ہونے پر ہے.چنانچہ لکھا ہے :.’’مسیح جو ہمارے لئے لعنتی بنا.اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا.‘‘(گلتیوں باب۳آیت ۱۳)
Page 285
جب شریعت لعنت ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ احکامِ شریعت بے حکمت اور بے مغز ہیں اور محض اللہ تعالیٰ نے انسان سے اپنی خدائی منوانے کے لئے یہ احکام دیئے تھے.انسان کا ان میں کوئی فائدہ نہیں تھا.اگر روزہ کا حکم دیا تو محض اس لئے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے بھوکا پیاسا تڑپتا رہے.ورنہ اس کا کوئی روحانی فائدہ نہیںتھا.پس عیسائیت شریعت کے احکام کے متعلق یہ سمجھتی ہے کہ نہ وہ انفرادی طور پر فائدہ مند ہیں اور نہ قومی طور پر.اور جب یہ حقیقت ہو تو احکام کا بجا لانا واقعی ایک مصیبت اورلعنت بن جاتا ہے.احکام تبھی رحمت ہوتے ہیں جب ان کی تعمیل کے نتیجہ میں انفرادی اور قومی فائدہ بھی ہو.جیسے اسلام کے احکام ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب اپنے اندر گہرا فلسفہ رکھتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ خدا تعالیٰ سے ملاتے ہیں بلکہ قومی ترقی اور حفاظت کے لئے بھی بہترین سامان مہیا کرتے ہیں.الغرض مسلمانوں اور کافروں کا طریق عبادت بالکل مختلف ہے مسلمانوں کے طریق عبادت میں دلی بشاشت قائم رہتی ہے.کیونکہ ان کی شریعت کے تمام احکام حکمت پر مبنی ہیں.اوران کے اندر معقولیت پائی جاتی ہے.پس ان حکمتوں اور معقولیت کی بنا پر مسلمانوں کی عبادت کافروں اور مشرکوں کی وہمی عبادت کی طرح نہیں ہو سکتی.گویا دونوں فریق بالطبع ایک دوسرے کے طریق کو اختیار نہیں کر سکتے.مسلم بصیرت کا عادی ہے وہ بے بصیرت عبادت کس طرح کر سکتا ہے اور کافر بے بصیرت عبادت کا عادی ہے وہ بصیرت والی عبادت کس طرح کر سکتا ہے.خلاصہ یہ کہ جو شخص اس عقیدہ پر قائم ہو کہ اِنْ تَکْفُرُوْا اَنْتُمْ وَ مَنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا فَاِنَّ اللّٰہَ لَغَنِیٌّ حَمِیْدٌ (ابراہیم:۹) یعنی خدا تعالیٰ انسانوں کی فرمانبرداری کا محتاج نہیں بلکہ وہی احکام اس نے نازل کئے ہیں جو لوگوں کے لئے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مفید ہیں.اور پھر جو شرک کو وجود باری کے منافی جانتا ہو وہ ان لوگوں کے ساتھ کیونکر عبادت میں متحد ہو سکتا ہے جن کے اوّل تو کوئی اصول ہی نہیں اور اگر کوئی اصول ہیں تو ان کا اپنا اختراع ہیں.غرض اللہ تعالیٰ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو حکم دیا ہے کہ وہ کسی زمانے میں کفر کے سامنے جھکیں نہیں بلکہ ان کی طرف سے پورے زور سے یہ اعلان ہونا چاہیے کہ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.اے منکرو! تم جو امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ مسلمانوں کو اپنے ادیان کی طرف مائل کر لو گے یہ غلط امیدیں ہیں.تم ہماری طرف سے کلیۃًمایوس ہو جاؤ.ہم تمہارے طریق عبادت کو کبھی اختیا رنہیں کر سکتے.یعنی تم جن اصول پر عبادت کرتے ہو ہم ان اصول پر عبادت کرنے کے لئے تیار نہیں.اور اس اعلان کی وجہ لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ میں بتادی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طوعی اطاعت کے طریق کو پیش کیا ہے تم اس کے منکر ہو.حالانکہ
Page 286
اس پر عمل کرنے سے بشاشت قلب قائم رہتی ہے اور صحیح الفکر انسان کا دل خود یہ چاہتا ہے کہ وہ ان پیش کردہ طریقوں پر گامزن ہو.کیونکہ احکام کے ساتھ ساتھ ان کی علّت اور وجہ بھی بتا دی گئی ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان احکام پر چلنے والے کو خدا تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کون کون سے قومی اور ملی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں.اس کے مقابل پر دوسرے مذاہب کے متبعین کے پاس جو احکام عبادت ہیں ان کی تعمیل میں نہ تو بشاشت قلب قائم رہ سکتی ہے اور نہ انسان خوشی خوشی ان کو اختیار کر سکتا ہے.کیونکہ ان احکام کی علت اور وجہ نہیں بتائی گئی اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان احکام پر چلنے والوں کو قومی یا ملی طور پر کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور جب یہ باتیں احکام میں نہ ہوں تو ایک عقل اور فکر سے کام لینے والا انسان ان احکام عبادت کو کیسے اختیار کر سکتا ہے.سوائے اس کے کہ عقل اور قوت فکر کو جواب دے دے.پس ایک مسلمان اعلیٰ درجہ کے احکام عبادت کی موجودگی میں غیر معقول احکام کو کیسے اختیار کر سکتا ہے اور اپنے بہترین دین کو چھوڑ کر ناقص ادیان کی اتباع کا خیال بھی ذہن میں کیسے لا سکتا ہے اور اسی بات کو لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ میںپیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے.لفظ دِیْن کے دوسرے معنے اَلسُّلْطَانُ وَ الْمُلْکُ وَالْحُکْمُ کے ہیں.اَلسُّلْطَانُ کے معنے لغت میں اَلْـحُجَّۃُ وَالتَّسَلُّطُ کے لکھے ہیں.یعنی دلیل اور غلبہ اور الْمُلْکُ وَالْـحُکْمُ کے معنے بادشاہت کے ہیں.(اقرب) ان معنوں کے اعتبار سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کی یہ تشریح ہو گی کہ (۱)اے منکرو اپنے معبودوں کی عبادت منوانے اور اپنی عبادت کے طریقوں پر دوسروں کو کاربند کرنے کے لئے تمہارے دلائل اور قسم کے ہیں اور توحید کو قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دنیا میں راسخ کرنے کے لئے میرے دلائل اور قسم کے ہیں.(۲)تمہارے تسلط کا نتیجہ اور ہے اور میرے تسلط کا نتیجہ اور.(۳)تمہارا طریق حکومت اور ہے اور میرا طریق حکومت اور.تمہارے اصول حکومت اور ہیں اور میرے اصول حکومت اور.گویا دین کے ان تینوں معنوںمیں تین اور مضبوط دلائل اس امر کے مہیا کئے گئے ہیں کہ کیوں ایک سچا مومن غیر مسلم کے ساتھ عبادت میں اشتراک نہیں کر سکتا.اورکیوں وہ ہر موقعہ پر ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ یعنی میں تمہارے ساتھ متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتا.جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے دین کے ایک معنے حجّت کے بھی ہیں.ان معنوں کو ملحفوظ رکھتے ہوئے آیت لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کی تشریح یہ ہو گی کہ اسلام کے منکرین کے پاس اپنے معبودوں کی عبادت منوانے اور اپنی عبادت
Page 287
کے طریقوں پر دوسروں کو کاربند کرنے کے لئے سوائے اکراہ اور جبر کے کچھ نہیں.اگر ان کے معبودوں کی عبادت سے کوئی سرتابی کرتا ہے یا اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو وہ اس کو جبر اور اکراہ اور ڈنڈے کے زور سے اپنے معبودوں کی طرف لانا چاہتے ہیں اور یہ طریق کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.خواہ وقتی طور پر انسان جبر کے آگے سر جھکا دے.لیکن جب دل سے اس کا مطیع نہیں ہوتا تو ہر موقعہ پر وہ اس قید سے آزاد ہونے کے لئے پوری جدوجہد کرتا ہے.انسان اس چیز کے سامنے صحیح طور پر جھکتا ہے جس کی دلیل اس کی سمجھ میں آجائے.اور جب وہ کسی چیز کو دلیل سے مانتا ہے تو پھر اس کا دل اور دماغ تسلی پا جاتا ہے لیکن منکرین اسلام اس کے خلاف اپنے معبودوں کی عبادت منوانے اور اسے رائج کروانے کے لئے کوئی ایسی دلیل تو پیش نہیں کرتے جو انسانی دل و دماغ کو مطمئن کر دے.ہاں ان کے پاس صرف ایک ہی طریق ہے کہ جو ان کے مذہب سے ذرا بھی ہٹا اس کو مارا پیٹا اور ذلیل کرنے کی کوشش کی اور اس کے آزار کے درپے ہو گئے اور اگر وہ ان کے سامنے نہ جھکا تو اس کی جان لینے کے منصوبے کرنے لگے.چنانچہ ابتدائے اسلام میں جب مسلمان پورے طورپر غیر مسلموں کے رحم پر تھے.ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا تھا.تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمانوں پر جو مظالم قریشِ مکہ کرتے تھے.وہ محض اس لئے تھے کہ وہ ان بتوں کی عبادت کی طرف پھر سے رجوع کریں جن کو چھوڑ کر وہ توحید اختیار کر چکے ہیں.چنانچہ بلال بن رباح جو امیہ بن خلف کے ایک حبشی غلام تھے.جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بتوں کی عبادت کو ترک کرکے خدائے واحد کی عبادت کا اقرار کیا.تو اُمیہ ان کو عین دوپہر کے وقت جبکہ اوپر سے آگ برستی تھی اور مکہ کا پتھریلا میدان بھٹی کی طرح تپتا تھا، باہر لے جاتا تھا اورننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا تھا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا تھا کہ لات اور عزّٰی کی پرستش کرو اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)سے علیحدہ ہو جاؤ.ورنہ اسی طرح عذاب دے دے کرمار دوں گا.بلالؓ زیادہ عربی نہ جانتے تھے.ان کے ظلم کے جواب میں وہ صرف اتنا کہتے اَحَد.اَحَد.یعنی اللہ ایک ہی ہے.اللہ ایک ہی ہے.امیہ یہ جواب سن کر اور تیز ہو جاتا اور ان کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں شریر لڑکوں کے حوالہ کر دیتا اور وہ ان کو مکہ کی پتھریلی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے.جس سے ان کا بدن خون سے تربتر ہوجاتا مگر ان کی زبان پر سوائے اَحَد.اَحَد کے کوئی اور لفظ نہ ہوتا.حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ جو ر و ستم دیکھ کر ان کو خرید لیا اور آزاد کر دیا.( البدایۃ والنـھایۃ باب امر اللہ رسولہ علیہ الصلاۃ والسلام بابلاغ الرسالۃ) اسی طرح خبابؓبن الارت جو پہلے غلام تھے پھر آزاد ہو گئے تھے.آہنگری کا کام کرتے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے.قریش مکہ نے ایک دفعہ ان کو ان کی بھٹی کے کوئلوں پر الٹا لٹا دیا اور ایک شخص ان کی چھاتی پر چڑھ گیا.
Page 288
تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکیں.چنانچہ وہ کوئلے اسی طرح جل کر ان کے نیچے ٹھنڈے ہو گئے اور ان کا چمڑہ اسی طرح ہوگیا جس طرح بھینسے کا ہوتا ہے.(الطبقات الکبرٰی ذکر خباب بن الارت رضی اللہ عنہ) الغرض مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ہوتے تا وہ توحید کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کریں.حتی کہ ان کو اپنی جائیدادوں سے محروم ہو کر اور اپنے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا اور پھر بھی مشرکین نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا.بلکہ لشکر اکٹھے کر کے ان پر حملہ آور ہو تے رہے.حتی کہ ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی جنگوں میں شہید ہو گئی.پس یہ سب کچھ اس لئے تھا کہ مشرکین اپنے طریق عبادت کو دوسروں کے گلے زبردستی منڈھنا چاہتے تھے.اور اپنی اکثریت اور طاقت کو اپنے حق پر ہونے کی دلیل سمجھتے تھے.لیکن مسلمان یہ کہتے تھے کہ عبادت کے منوانے اور اس پر کاربند کروانے میں زبردستی نہیں ہونی چاہیے.بلکہ پوری آزادی دی جانی چاہیے اور دلائل سے قائل کرنا چاہیے کہ کیوں عبادت کا فلاں طریق اختیار کیا جائے.اگر مخاطب کی سمجھ میں وہ بات آجائے تو اس کو تسلیم کر ے وگرنہ چھوڑ دے.اور مسلمان اپنے مذہب کی تبلیغ کے ضمن میں اسی طریق کو اختیار کرتے تھے.بتوں کی عبادت کے خلاف جو وعظ ہوتا اس میں یہی بات بیان کی جاتی کہ یہ پتھر کے بت تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو.یہ نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ دعا کو قبول کرتے ہیں.پس ان کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ.عبادت تو اس ہستی کی کرنی چاہیے جو دعاؤں کو سنے.تکلیف کو دور کرے اور احسان کرنے اور نفع پہنچانے پر قادر ہو.اور ایسی ہستی سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں.مسلمان قرآن کریم کے اس حکم پر پوری طرح عامل تھے کہ لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ(البقرۃ:۲۵۷) یعنی عبادت کے معاملہ میں جبر نہیں ہونا چاہیے بلکہ دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے.کیونکہ قرآن کریم اس تعلیم کو بار بار پیش کرتا ہے.چنانچہ فرماتا ہے :.لِيَـهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّ يَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ (الانفال:۴۳) یعنی جنگ بدر میں جو معجزات ہم نے دکھائے وہ محض اس لئے تھے تاکہ جو ہلاک ہو وہ صرف تلوار سے ہلاک نہ ہو بلکہ دلیل سے ہلاک ہو.اور جو زندہ ہو وہ صرف تلوار سے بچ کر زندہ نہ ہو بلکہ دلیل سے زندہ ہو.گویا اس آیت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ شکست و فتح دلائل کے رو سے ہونی چاہیے اور اصل شکست یہی ہے کہ انسان کے پاس دلائل نہ ہوں.اور اصل جیت یہی ہے کہ انسان کے پاس دلائل ہوں اور وہ دوسروں کو قائل کرلے.پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ١ؕ قُلْ لَّاۤ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ١ۙ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ.قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ كَذَّبْتُمْ
Page 289
بِهٖ (الانعام:۵۷،۵۸) یعنی اے نبی اعلان کر دو کہ مجھے تمہارے بتوں کی عبادت کرنے سے روکا گیا ہے.تم محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ان کی عبادت بجا لاتے ہو.تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں اور اگر میں بھی تمہارے پیچھے چلوں تو میں بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں.اے نبی اعلان کر دو کہ میں نے تو جس راستے کو اختیار کیا ہے یعنی توحید کو اس کے لئے میرے پاس کھلے کھلے دلائل ہیں لیکن تم ان کا انکار کر رہے ہو.پس اسلام تو دلائل کو پیش کرتا ہے اور ان دلائل کے پیش کرنے کے بعد کہتا ہے.مَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ (الکہف:۳۰) کہ جس کی سمجھ میں یہ دلائل آتے ہیں وہ اسلام کی پیش کردہ تعلیم کو مان لے اور جس کی سمجھ میں وہ دلائل نہیں آتے، بےشک وہ اپنی اختیار کردہ راہ پر قائم رہے.کفار کے نرغہ میں جب کوئی مسلمان پھنس جاتا اس کو زبردستی اقرار کرانے کی کوشش کرتے کہ وہ خدائے واحد کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرے گا.لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے وَ اِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ (التوبۃ:۶) کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں طاقت دے اور پھر کوئی مشرک تمہارے ہاں پناہ گزین ہو تو اس کو پناہ دو اور اس کی بہترین مہمانی اس طور پر کرو کہ قرآنی تعلیم کو اس کے سامنے پیش کرو.پھر اس پر اس کو منوانے کے لئے کوئی جبر نہ کرو بلکہ اس کے اپنے علاقہ میں جہاں اسے امن حاصل ہے پہنچا دو.مسلمان مذہبی آزادی قائم رکھنے پر پوری طرح عامل تھے.چنانچہ مدینہ میں جب اسلام پھیلا اور مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے جبر و اکراہ سے کام نہیں لیا.مدینہ میں یہ طریق تھا کہ کسی اوسی یا خزرجی(مشرکین مدینہ) کے ہاں اگر اولاد نرینہ نہ ہوتی تو وہ منت مانتاتھا کہ اگر اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ اسے یہودی بنا دے گا.اس طرح اوس اور خزرج کے کئی بچے یہودی بن گئے.مسلمانوں کی طاقت کے زمانہ میں جب بنو نضیر یہودی اپنی شرارتوں کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کئے گئے تو ان میں وہ بچے بھی تھے جو انصار کی اولاد تھے اور انصار نے انہیں روک لینا چاہا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ کی آیت کے ماتحت ایسا کرنے سے روک دیا.(السیرۃ الـحلبیۃ فی ذکر غزوۃ بنی النضیر و تفسیر الخازن زیر آیت لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ)پھر مدینہ میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو ان کی عبادت کا وقت آنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کو عبادت بجا لانے کی اجازت دےدی.اور جب بعض صحابہ ؓ نے روکنا چاہاتو آپ نے ان صحابہ کو منع فرما دیا.چنانچہ ان عیسائیوں نے مشرق رُو ہو کر عین مسجد نبوی میں اپنی عبادت کے مراسم ادا کئے.(شرح زرقانی حالات وفد نجران)
Page 290
پس اسلام مذہبی آزادی کا قائل ہے.وہ اپنی تعلیم اور عبادت کو دلائل قویہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش تو کرتا ہے لیکن اس پر چلانے کے لئے جبر و اکراہ کا قائل نہیں اور اگر کوئی ایسی تعلیم کو قبول کرلینے کے بعد پھر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اس پر کسی قسم کی گرفت نہیں کرتا.لیکن مشرکین اس کے مقابل پر اپنی عبادت کو ڈنڈے کے زور سے منواتے اور اس پر کاربند ہونے کے لئے مجبور کرتے ہیں.اور اگر کوئی ان کی عبادت سے نفرت کرتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے تو اس کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں.اَلسُّلْطَانُ کے دوسرے معنے اَلتَّسَلُّطُ کے ہیںاس معنے کے اعتبار سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کی یہ تشریح ہوگی کہ اے منکرو! تمہارا تسلط کا طریق اور ہے اور میرا تسلط کا طریق اور.تمہارے تسلط کے نیچے حریت ضمیر باقی نہیں رہتی لیکن میرے تسلط میں حریت ضمیر کو قائم کیا جاتا ہے.ان دو متضاد نظریوں کے ساتھ ہم عبادت کس طرح اکٹھے کر سکتے ہیں.تم تو خدا سے یہ دعا کرو گے کہ الٰہی ہم کو اپنے مخالفوں پر غلبہ بخش تاکہ جبراً ان کا مذہب بدلوا دیں اور میں یہ دعا کروں گاکہ الٰہی مجھے منکروں پر غلبہ بخش تاکہ میں حریت ضمیر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرسکوں.پھراللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے.اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْھِمْ سُلْطٰنٌ (الـحجر:۴۳) کہ میرے بندوں پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا.یعنی غیر مومنوں پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے.اور یہ ظاہر ہے کہ جن پر شیطان کا تسلط ہو جائے وہ دوسروں پر غالب آکر شیطانی تسلط کو قائم کریں گے.پس تسلط کے اس معنے کے مدّ ِنظر لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے یہ معنے بھی ہوں گے کہ میں خدا کا تسلط دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہوں اور منکرین اسلام شیطان کا تسلط قائم کرتے ہیں پس دونوں فریق متحد فی العبادۃ کس طرح ہو سکتے ہیں.(۲)جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے لفظ دِیْن کے ایک معنے اَلْمُلْکُ وَالْـحُکْمُ یعنی بادشاہت اور حکومت کے ہیں اس مفہوم کے لحاظ سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے یہ معنے ہوں گے کہ اے اسلام کے منکرو! تمہارا طریق حکومت اور اصول حکومت اور ہے اور میرا طریق حکومت اور اصول حکومت اور ہے یعنی تمہارے ہاں استبداد جائز ہے لیکن میرے نزدیک ہر فرد کو حکومت میں رائے دینے کا حق ہے اور انتخاب کا طریق جائز ہے.تم لٹھ بازی سے کام چلاتے ہو اور اپنے جتھوں کے سہارے ملکوں پر قبضہ کر لیتے ہو.تمہاری حکومتیں اوّل تو نیا بتی نہیں ہوتیں اور اگر کہیں ہوں بھی تو سارے ملک کی نمائندہ نہیں ہوتیں.تم اپنی حکومتوں میں اپنے ما تحتوں کے حقوق کا پوری طرح خیال نہیں رکھتے اور اس وجہ سے ہمیشہ تمہارے خلاف ملکوں میں بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں اور ر عایا اور حکومت کی چپقلش رہتی ہے.تم میں سے جب کوئی حاکم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مقام کو عام لوگوں سے بہت بلند خیال کرنے لگتا ہے تم لوگ جب کسی
Page 291
دوسری حکومت سے معاہد ہ کرتے ہو تو اس کی پروا نہیں کرتے اور جب تمہیں اپنا مفاد ضائع ہوتا نظر آتا ہو تو وہاں فوراً معاہدہ کو توڑ دیتے ہو.تمہارے پاس کوئی ایسے صحیح قوانین اور ٹھوس ذرائع نہیں جن سے تمہارے اپنے ملک کے اندر اور تمہارے ہمسایہ ملکوں میں امن برقرار رہ سکے.ہم تو ایسی جابرانہ حکومتوں کے خلاف ہیں اور ہم ان سے لوگوں کو آزاد کروا کر ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی مرضی کے عین مطابق ہو.وہ اپنے ملک کی نمائندہ ہو اپنے ما تحتوں کی ضروریات کا پوری طرح خیال رکھے.لوگ اس کے ماتحت رہنا فخر و عزت خیال کریں.اس میں حاکم و محکوم کے درمیان کوئی خلیج حائل نہ ہو.وہ اپنے معاہدوں کی پابندی کرنے والی ہو.اور صرف اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ اپنے ہمسایہ ملکوں میں بھی امن کو قائم کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو.پس اس اختلاف کے ہوتے ہوئے ہمارے اور تمہارے درمیان اتحاد فی العبادۃ کیونکر ہو سکتا ہے.تمہاری عبادت کے نتیجہ میں دنیا میں ظلم کے راستے کھلتے ہیں اور میری عبادت ظلم کے راستوں کو بند کرتے ہوئے امن کی علمبردار ہے.یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب سورۃ کافرون نازل ہوئی تھی.اس وقت تو مسلمانوں کی حالت نہایت کمزور تھی اور وہ مکہ میں جا بجا ماریں کھاتے پھرتے تھے.اس وقت مسلمانوں کو یہ خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ ہم ایسی حکومت قائم کر لیں گے جو امن کا گہوارہ ہو اور جنت کا نمونہ ہو.اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک مسلمانوں کی حالت نہایت ضعف کی تھی اور ان کے مخالفین پورے جوبن پر تھے.عرب میں قبائلی حکومت تھی اور عرب سے باہر دواہم طاقتیں تھیں(۱)کسریٰ ایران کی طاقت(۲)اور قیصر روم کی طاقت.لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ جلد ہی مسلمانوں کی ضعف کی حالت طاقت میں تبدیل ہو جائے گی اور وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے اور مسلمان اس وعدے پر پورا یقین اور وثوق رکھتے تھے اور اس دن کو قریب سمجھتے تھے جب ان کی ایک ایسی طاقتور حکومت قائم ہوجائے گی جو جبر و استبداد کا قلع قمع کر کے دنیا میں امن قائم کردے گی.چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ وعدہ کیا گیا تھا.اس کا ذکر واضح الفاظ میں سورۂ نور میں (جو مدینہ میں نازل ہوئی) کیا گیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :.وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ١۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا١ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ۠ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا١ؕ وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (النور:۵۶) کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ
Page 292
علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرورملک میں بادشاہ بنا دے گا.وہ ایسی شان اور عظمت رکھنے والے بادشاہ ہوں گے جیسے پہلی منعم علیہ قوموں میں ہوئے ہیں.ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اسلام کے اعلیٰ اور افضل احکام جاری کر دے گا اور اس وقت جو مسلمانوں کی خوف کی حالت ہے یا آئندہ جو بھی خوف کی حالت پیدا ہو گی اس کو امن میں بدل دے گا.یہ بادشاہ میری عبادت کو دنیامیں قائم کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے.پس ان انعامات کے بعد جو میری نعمتوں کی ناشکری کرے گا اور صحیح طریق حکومت کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرے گا وہ فاسق ہو گا.مذکورہ بالا آیت میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ یعنی وہ ان کو ملک میں خلفاء بنادے گا.خلفا ء خلیفہ کی جمع ہے اور خلیفہ کے معنے ہیں:.۱.مَنْ یَّـخْلُفُ غَیْرَہٗ وَ یَقُوْمُ مَقَامَہٗ یعنی جو کسی کے قائم مقام ہو کر وہی کام کرے جو اصل وجود کام کر رہا ہوتا ہے.۲.وَالسُّلْطَانُ الْاَعْظَمُ.سب سے بڑا بادشاہ.۳.وَ فِی الشَّـرْعِ الْاِمَامُ الَّذِیْ لَیْسَ فَوْقَہٗ اِمَامٌ اور شرعی اصطلاح میں خلیفہ اس امام کو کہتے ہیںجس کے اوپر اس زمانہ میں کوئی امام نہ ہو(اقرب) پھر اَلْـخِلَافَۃُ کے معنے کرتے ہوئے اقرب الموارد میں لکھا ہے :.۱.اَلْاِمَارَۃُ.یعنی خلافت کے ایک معنے حکومت کے ہیں.۲.اَلنِّیَابَۃُ عَنِ الْغَیْرِ اِمَّا لِغَیْبَۃِ الْمَنُوْبِ عَنْہُ اَوْ لِمَوْتِہٖ.کہ خلافت کے معنے ہیں کسی کا نائب اور قائم مقام ہو کر وہی کام کرنا جو اصل وجود کام کر رہا تھا.اور یہ نیابت یا تو اس لئے ہو کہ اصل وہاں موجود نہیں یا اصل وفات پا گیا ہے.اب اس کے کام کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے.(اقرب) پس لغت کے ان معنوں کے لحاظ سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کے مندرجہ ذیل معنے ہوں گے :.۱.اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ملک میں بہت بڑے خلفاء اور بادشاہ بنادے گا.۲.یہ بادشاہت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہو گی.یعنی جو کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دے رہے ہیں.وہی کام ان کو سر انجام دینا ہوگا.الغرض مومنوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکومت عطا کرے گا اور وہ حکومت بھی الٰہی منشاء کے
Page 293
مطابق ہو گی.پھر مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ کے الفاظ میں یہ بھی بتا دیا کہ خلافت درحقیقت خدا تعالیٰ کی نمائندگی میں ہوتی ہے اور خدا کی صفات کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے.جو اس کا انکار کرتا ہے وہ درحقیقت خدا تعالیٰ سے عہد مودّت توڑتا ہے.احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بعد خلافت ہوگی یعنی ایسے وجود ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کوجاری رکھنے والے ہوں گے.لیکن ان کے بعد یہ حالت بدل جائے گی.اور دوسری قوموں کی نقل میں مسلمان بھی استبدادی حکومت کے شائق ہو جائیں گے.لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ صحیح خلافت کو قائم کرے گاجو خدا تعالیٰ کے منشاء کو پورا کرنے والی ہو گی چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:.قَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ تَکُوْنُ النُّبُوَّۃُ فِیْکُمْ مَاشَآءَ اللہُ اَنْ تَکُوْنَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا اللہُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوْنُ خِلَافَۃٌ عَلٰی مِنْـھَاجِ النُّبُوَّۃِ مَاشَآءَ اللہُ اَنْ تَکُوْنَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا اللّٰہُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوْنُ مُلْکًا عَاضًّا مَاشَآءَ اللہُ اَنْ یَّکُوْنَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا اللّٰہُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوْنُ مُلْکًا جَبْرِیَّۃً فَیَکُوْنُ مَاشَآءَ اللہُ اَنْ یَّکُوْنَ ثُمَّ یَرْفَعُھَا اللہُ تَعَالٰی ثُمَّ تَکُوْنُ خِلَافَۃٌ عَلٰی مِنْھَاجِ النُّبُوَّۃِ.(مشکوٰۃ کتاب الرقاق باب الانذار و التـحذیر الفصل الثالث ) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عرصہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے نبوت کا زمانہ رہے گا.پھر خلافت نبوت کے طریق پر قائم ہو گی اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا منشاء ہو گا.پھر وہ ختم ہو جائے گی اور بادشاہت کا دروازہ کھل جائے گا.اوریہ کچھ عرصہ تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کھلا رہے گا.پھر اس کے بعد جابر حکومتیں شروع ہو جائیں گی.پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا اور اس کے بعد دوبارہ نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہو گی.چنانچہ یہ وعدے پورے ہوئے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمانوں کو حکومت مل گئی اور آپ کے بعد کچھ عرصہ تک یہ حکومت قائم رہی.لیکن بعد ازاں یہ حکومت عام دنیوی حکومتوں کی طرح بن گئی.اب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے اور پیشگوئی کے مطابق آپ کے ذریعہ ایسی حکومتوں کی بنیاد پڑے گی جو بجائے دنیا کی طالب ہونے کے روحانی اور اخلاقی اقدار کو قائم کرنے کی کوشش کریں گی اور ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو جائے گا.غرض یہ سب وعدے چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے اس لئے بہرحال انہوں نے پورا ہونا تھا اور مسلمان ان پر پورے وثوق و یقین سے قائم تھے اور اسی کے پیشِ نظر ان کو ابتدائی زمانہ میں ہی یہ اعلان کرنے کا حکم دے دیا
Page 294
گیا کہ اے منکرو! لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ.تمہاری ظالمانہ حکومت تمہی کو سجتی ہے.ہم تو ظلم و استبداد کو جائز نہیں سمجھتے.بلکہ اس کو مٹانے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں.تمہاری حکومتوں میں مذہبی آزادی نہیں اور مسلمان ایسی حکومتوں سے نہ صرف خود آزاد ہونا چاہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی آزاد کرائیں گے اور ایسی حکومت قائم کریں گے جو ہر قسم کی خیر و برکت اپنے اندر لئے ہوئے ہو گی.چنانچہ اسلام کے ذریعہ جو حکومت قائم ہو ئی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی اور یہودی خود چاہتے تھے کہ اسی حکومت کے ماتحت رہیں.تاریخوں میں آتا ہے کہ ملک شام کی فتوحات میں جب حمص پر قبضہ کے بعد دوبارہ دشمن کے حملہ کا خطرہ ہوا.تو مسلمانوں نے حمص کو خالی کر دیا اور وہاں کے عیسائی باشندوں سے جو جزیہ لیا گیا تھا وہ سب کا سب واپس کر دیا.اور ان کو کہہ دیا کہ یہ رقم ہم نے اس معاہدہ کے ماتحت لی تھی کہ مسلمان تمہاری حفاظت کریں گے.لیکن اس وقت ہماری ایسی نازک حالت ہے کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے.اس لئے تمہیں تمہاری رقم واپس کی جاتی ہے.چنانچہ کئی لاکھ کی رقم جو وصول کی گئی تھی واپس کر دی گئی.عیسائیوں پر اس واقعہ کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ روتے جاتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے.یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر ہوا.انہوں نے کہا کہ توراۃ کی قسم جب تک ہم زندہ ہیں قیصر حمص پر قبضہ نہیں کر سکتا.(فتوح البلدان بلاذری یوم الیرموک صفحہ ۸۷) پس ان واقعات سے اور ان جیسے دوسرے واقعات سے جو تاریخوں میں ملتے ہیں یہ ثابت ہے کہ اسلامی حکومت لوگوں کے دلوں کو فتح کرتی تھی.ملک سے ظلم و استبداد کو ختم کرتی تھی.مذہبی آزادی برقرار رکھتی تھی.اپنے معاہدوں کی پابندی کرتی تھی.جس کی وجہ سے وہ ملک امن کا گہوارہ بن جاتا تھا.اور ملکوں کے باشندے دل سے اس حکومت کو چاہتے تھے.اسلامی حکومت کے گیارہ اصول پھر اسلام نے حکومت کے جو اصول پیش کئے ہیں.وہ اتنے اعلیٰ اور ارفع ہیں کہ جو حکومت ان اصولوں پر قائم ہو گی وہی دنیا کی ترقی اور امن کی ضامن ہو سکتی ہے.چنانچہ وہ اصول یہ ہیں:.۱.پہلا اصل اسلام نے حکومت کا یہ پیش کیا ہے کہ حکومت انتخابی ہو اور حکومت کی بنیاد اہلیت پر ہو.۲.دوسرا اصل اسلام نے حکومت کا یہ پیش کیا ہے کہ حکومت کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ ایک امانت ہے.گویا اسلام کے نزدیک نسلی اور موروثی بادشاہت نہیں ہے.۳.حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کرے.۴.حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ افراد اور اقوام کے درمیان عدل کرے.
Page 295
۵.قومی معاملات مشاورت سے طے ہوں.۶.حکومت ہر ایک شخص کے لئے خوراک، لباس اور مکان مہیا کرنے کی ذمہ دار ہو.۷.دوسروں کے ممالک پر طمع کی نظر نہ رکھی جائے.جنگ صرف دفاعی ہو.۸.مفتوح کے ساتھ عدل کا سلوک کیا جائے.۹.جنگی قیدیوں کو خاص طور پر مراعات دی جائیں.۱۰.معاہدات کی پابندی کی جائے.۱۱.ملک میں مذہبی آزادی قائم کی جائے.یہ وہ اصول ہیں جن کو اسلام نے حکومت کے لئے ضروری قرار دیا ہے.چنانچہ پہلے چار اصولوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا١ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا (النسآء:۵۹) یعنی اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تمہیں موقعہ ملے کہ تم حکومت کی امانتیں کسی کے سپرد کرو.تو یاد رکھو کہ تم یہ امانتیں ہمیشہ ان لوگوں کے سپرد کرو جو تمہارے نزدیک حکومت کے اہل ہوں.اور جن کے اندر یہ قابلیت پائی جاتی ہو کہ وہ حکومتی کاموں کو عمدگی سے سرانجام دے سکیں.اور جب اے حاکمو!تم حاکم ہو جاؤ تو تم انصاف کے ساتھ حکمرانی کرو.اللہ تعالیٰ جس امر کی تم کو نصیحت فرماتا ہے وہ بہت اچھا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے.اس آیت میں پہلے تو عامۃ الناس کو مخاطب کیا ہے کہ حاکم بنانا تمہارا کام ہے اور تمہارے اختیار میں ہے.تمہارے سوا اور کوئی شخص حاکم بنانے کا مجاز نہیں.یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص زبردستی حاکم بن جائے اور پھر وراثۃً حکومت چل پڑے.یہ طریق درست نہیں اور نہ کسی شخص کا حق ہے کہ محض کسی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے لوگوں کی گردنوں پر حکومت کا جؤا رکھے.دوسرا امر یہ بتایا کہ یہ حکومت کے حقوق ایک قیمتی چیز ہیں جس طرح کہ امانت قیمتی ہوتی ہے پس فرقہ وارانہ جذبات سے علیحدہ ہو کر اس امانت کو حق دار کے سپرد کرنا چاہیے.کسی ایسے شخص کے سپرد نہ کرنا جو اس کے قابل نہ ہو.اور یہ مدّ ِنظر نہ ہو کہ یہ شخص ہماری پارٹی کا نہیں ہے.اس لئے ہم اس کو یہ امانت نہیں دیں گے بلکہ اس شخص کے سپرد کرو جو دیانت داری سے امانت کی حفاظت کر سکے.تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ حکومت کوئی مستقل چیز نہیں ہے بلکہ ان حقوق کو کسی شخص کے سپرد کر دینے کا نام
Page 296
ہے جن کو بوجہ بہت سے لوگوں کے اشتراک کے لوگ فرداً فرداً ادا نہیں کر سکتے.اس لئے اس کو امانت خیال کرنا چاہیے.کیونکہ وہ حقوق و فرائض جن کے مجموعہ کا نام حکومت ہے کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں.بحیثیت مجموعی جماعت ان کی مالک ہے.چوتھا حکم حاکم کو یہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم کو دیا جاتا ہے.وہ چونکہ بطور امانت کے ہے اس لئے اس کو اسی طرح محفوظ بلا خراب یا تباہ کرنے کے اپنی موت کے وقت واپس دینا ہوگا.یعنی حکومت کی پوری حفاظت اور اہل ملک کے حقوق کی نگرانی رکھنی ہو گی.اور یہ تمہارا اختیار نہ ہوگا کہ اس حق کو ضائع کردو.پانچواں امر اس آیت سے یہ نکلتا ہے کہ حکام کو چاہیے کہ دوران حکومت میں لوگوں کے حقوق کو پوری طرح ادا کریں اور کسی قسم کا فساد پیدا نہ کریں.یہ نہ ہو کہ کسی فرد کی ناجائز طرف داری کرتے ہوئے اسے بڑھا دیں اور کسی کو نیچے گرا دیں.کسی قوم کو اونچا کر دیں اور کسی قوم کو نیچا کر دیں.کسی قوم میں تعلیم پھیلا دیں اور کسی قوم کو جاہل رکھیں.کسی کی اقتصادی ضروریات کو پورا کریں اور کسی کی اقتصادی ضروریات کو نظر انداز کر دیں.بلکہ جب لوگوں کے حقوق کا فیصلہ کیا جائے تو ہمیشہ عدل اور انصاف سے فیصلہ کیا جائے.رعایت یا بے جا طرف داری سے کام نہ لیا جائے.الغرض اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت انتخابی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی نیابتی بھی.یعنی حکمران ملک کے لوگوں کا ان کی مجموعی حیثیت میں نہ کہ بحیثیت افراد نائب ہے.پھر جو شخص منتخب ہو.وہ حکومت کو اپنی اولاد میں نسلاً یا وراثۃً منتقل نہیں کر سکتا.بلکہ اس کی وفات پر وہ امانت قوم کے سپرد ہو گی اور قوم جس کو اس کا اہل سمجھے گی انتخاب کر ے گی.یورپ اور دیگر ممالک میں آج کل یا توڈکٹیٹرشپ ہے یا وراثتی بادشاہت یا خالصۃً جمہوریت.لیکن اسلام ڈکٹیٹرشپ اور وراثتی بادشاہت کے بالکل خلاف ہے.اسلام جمہوریت کو پیش کرتا ہے.لیکن اس جمہوریت سے قدرے مختلف جس کو آج کل کے متمدن ممالک اپنی فوقیت کی دلیل قرار دیتے ہیں.ان ممالک میں پارٹی بازی ہوتی ہے اور ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ ان کی پارٹی کا لیڈر منتخب ہو جائے.خواہ قابل اور حکومت کا اہل دوسرے فریق کا لیڈر ہو.لیکن اسلام اس بات کے بالکل خلاف ہے.اسلام کہتا ہے کہ فرقہ وارانہ جذبات سے الگ ہو کر محض قابل، لائق اور اہل شخص کو منتخب کیا جائے.پھر ان ممالک میں پریذیڈینٹوں کا انتخاب محض چند سالوں کے لئے ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک قابل دماغ بے کار ہو جاتا ہے اور اس کو ٹھکرا دیا جاتا ہے.لیکن اسلامی آئین کی رُو سے جو منتخب ہو گا وہ ساری عمر کے لئے ہو گا.
Page 297
اور اس شخص کا فرض ہو گا کہ اپنی ساری عمر کو ملک کی بہتری کے لئے صَرف کر دے نہ کہ اپنی بڑائی کے حصول کے لئے.لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ خلافت روحانی اور ملکی اختیارات ایک شخص کے ہاتھ میں ہوں.دوسری صورت میں جبکہ صرف ملکی اختیارات کا سوال ہو.پریذیڈنٹ یا صدر مملکت تھوڑے عرصہ کے لئے بھی مقرر کیا جا سکتا ہے.لیکن اس کے انتخاب میں پھر بھی یہی بات مدّ ِنظر رہنی چاہیے کہ اس کا انتخاب موجودہ مغربی ممالک کی پارٹی بازی کے طریق پر نہ کیاجائے بلکہ خالصۃً اہلیت کو مدّ ِنظر رکھا جائے.اور یہ کوشش کی جاتی رہے کہ ہمیشہ ملک کا بہترین دماغ قومی خدمت کے لئے آگے آتا رہے.پس اسلامی اصول حکومت آج کل کے متمدن ممالک کے اصولوں سے مختلف ہیں اور ان سے بہتر ہیں.اور ہمارے نزدیک جمہوریت کے مدعی ممالک میں جو طریق حکومت رائج ہے وہ درست نہیں.پھر اسلام کا حکم ہے کہ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ (الشورٰی: ۳۹) کہ حکومت کے معاملات مشورہ سے طے ہونے چاہئیں.یعنی منتخب شدہ شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک مجلس شوریٰ کے ذریعہ سے ملک کی عام رائے کو معلوم کرتا رہے اور جب ضرورت ہو عام اعلان کر کے تمام افراد سے ان کی رائے دریافت کرے.تاکہ اگر کسی وقت ملک کے نمائندوں اور ملک کی عام رائے مخالف ہو جائے تو ملک کی عام رائے کا علم ہو سکے.پھر اگر نیابتی فرد کے وجود میں روحانی اور ملکی اختیارات دونوں جمع ہوں.تو وہ مشیرکاروں کی کثرت رائے کو ردّ کرسکتا ہے.کیونکہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت ملتی ہے اور اس کو ہر قسم کی سیاسی جنبہ داری سے بالا سمجھا جاتا ہے اور اس کی رائے کی نسبت یقین کیاگیا ہے کہ وہ تعصب سے پاک ہو گی اور محض ملک و ملت کا فائدہ اسے مدّ ِنظر ہو گا.لیکن اگر وہ انتخابی فرد صرف پریذیڈنٹ یا صدر مملکت ہو تو وہ اس آئین کا پابند ہو گا جس کے ماتحت اس کا تقرر ہوا.پھر اسلام نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسلامی حکومت اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ ہر اک شخص کے لئے خوراک، لباس اور مکان مہیا کرے.یہ ادنیٰ سے ادنیٰ ضروریات ہیں جن کا پورا کرنا حکومت کے ذمہ ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ چیز جس کی حفاظت اس کے سپرد کی گئی ہے زندہ نہیں رہ سکتی.مکان اور خوراک کے بغیر جسمانی زندگی محال ہے اور لباس کے بغیر اخلاقی اور تمدنی زندگی محال ہے.اسلام کا یہ حکم قرآن کریم کی اس آیت میں پایا جاتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَ لَا تَعْرٰى وَ اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَ لَا تَضْحٰى ( طٰہٰ:۱۱۹،۱۲۰) یہ آیت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آئی ہے.
Page 298
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اے آدم ہم نے تمہارے جنت میں رکھے جانے کا فیصلہ کر دیا ہے.تم اس میں بھوکے نہیں رہوگے، تم اس میں ننگے نہیں رہو گے، تم اس میں پیاسے نہیں رہو گے اور تم اس میں رہنے کی وجہ سے دھوپ میں نہیں پھروگے.لوگ اس آیت سے غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مرا د اخروی جنت ہے اور آیت کا یہ مطلب ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا تو وہاں اس کا یہ حال ہوگا.حالانکہ قرآن کریم سے صاف ظاہر ہے کہ آدم اسی دنیا میں پیدا ہوئے تھے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (البقرۃ:۳۱) میں دنیا میں اپنا خلیفہ مقررکرنے والاہوں.اور دنیا میں جو شخص پیدا ہوتا ہے.وہ بھوکا بھی ہو سکتا ہے، وہ پیاسا بھی ہو سکتا ہے، وہ ننگا بھی ہوسکتا ہے، وہ دھوپ میں بھی پھر سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں تو پیدا ہو اور بھوک اور پیاس اور لباس اور مکان کی ضرورت اسے نہ ہو.اور جبکہ یہ آیت اسی دنیا کے متعلق ہے تو لازماً ہمیں اس کے کوئی اور معنے کرنے پڑیں گے اور وہ معنے یہی ہیں کہ ہم نے اپنا پہلا قانون جو دنیا میں نازل کیا.اس میں ہم نے آدمؑ سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم ایک ایسا قانون تمہیں دیتے ہیں کہ جو تجھ کو اور تیری امت کو جنت میں داخل کر دے گا اور وہ قانون یہ ہے کہ ہر ایک کے کھانے پینے، لباس اور مکان کا انتظام کیا جائے.آئندہ تم میں سے کوئی شخص بھوکا نہیں رہنا چاہیے بلکہ یہ سوسائٹی کاکام ہے کہ ہر ایک کے لئے غذا مہیا کرے.آئندہ تم میں سے کوئی شخص ننگا نہیں رہنا چاہیے بلکہ یہ سوسائٹی کا کام ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے لئے کپڑا مہیا کرے.آئندہ تم میںسے کوئی شخص پیاسا نہیں رہنا چاہیے بلکہ یہ سوسائٹی کا کام ہونا چاہیے کہ وہ تالابوں اور کنوئوں وغیرہ کا انتظام کرے.آئندہ تم میں سے کوئی شخص بغیر مکان کے نہیں رہنا چاہیے.بلکہ یہ سوسائٹی کاکام ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک کے مکان کا انتظام کرے.گویا یہ وہ پہلا تمدّن ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعہ دنیا میں قائم کیا گیا.اور اللہ تعالیٰ نے دنیا پر اس حقیقت کو ظاہر فرمایا کہ خدا سب کا خدا ہے.وہ امیروں کا بھی خدا ہے، وہ غریبوں کا بھی خدا ہے، کمزوروں کا بھی خدا ہے اور طاقتوروں کا بھی خدا ہے.وہ نہیں چاہتا کہ دنیا کا ایک طبقہ تو خوشی میںاپنی زندگی بسر کرے اور دوسرا روٹی اور کپڑے کے لئے ترستا رہے.چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم ثانی ہیں.ان پر بھی قرآن کریم میں یہ آیات نازل کر کے آپ کو کہا گیا کہ آپ کو بھی ایسا تمدّن قائم کرنا ہو گا.جس میں ہر ایک کے لئے لباس، مکان اور خوراک کا انتظام کیا جائے.چنانچہ مدنی زندگی میں جب عرب کے علاقہ بحرین کا رئیس مسلمان ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایات بھجوائیں، اور لکھا :.اِفْرِضْ عَلٰی کُلِّ رَجُلٍ لَیْسَ لَہٗ اَرْضٌ اَرْبَعَۃُ دَرَاھِمَ وَعَبَاءَۃٌ.(شرح زرقانی، تابع الفصل السادس: فی امرائہٖ و رسلہ.....) یعنی جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے.ان میں سے ہر ایک کو ملکی خزانہ میں سے چار درہم اور لباس
Page 299
گذارہ کے لئے دے دیا جایا کرے ( اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کے پاس زمین نہیں صرف اسی کی مدد کر نی چاہیے.بلکہ جس کی زمین ہو اور وہ تباہ ہو جائے یا فصل ہو اور وہ تباہ ہو جائے.وہ بھی بمنزلہ اس کے ہوگا جس کی زمین نہیں کیونکہ نتیجہ میں وہ اس کے مشابہ ہے جس کی زمین نہیں ) پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب نظام مکمل ہوا.تو اس وقت اسلامی تعلیم کے ماتحت ہر فرد بشر کے لئے روٹی اور کپڑا مہیا کرنا حکومت کے ذمہ تھا اور وہ اپنے اس فرض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیا کرتی تھی.حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غرض کے لئے مردم شماری کا طریق جاری کیا اور رجسٹرات کھولے جن میں تمام لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوا کرتا تھا.یورپین مصنّفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی اور انہوں نے ہی رجسٹرات کا طریق جاری کیا.اس مردم شماری کی وجہ یہی تھی کہ ہرشخص کو روٹی کپڑا دیا جاتا تھا اور حکومت کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس بات کا علم رکھے کہ کتنے لوگ ملک میں پائے جاتے ہیں.آج یہ کہا جاتا ہے کہ سویٹ رشیا نے غرباء کے کھانے اور ان کے کپڑے کا انتظام کیا ہے حالانکہ سب سے پہلے اس قسم کا اقتصادی نظام اسلام نے جاری کیا تھا.اور عملی رنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہرگائوں، ہر قصبہ اور ہر شہر کے لوگوں کے نام رجسٹر میں درج کئے جاتے تھے.ہر شخص کی بیوی اس کے بچوں کے نام اور ان کی تعداد درج کی جاتی تھی اور پھر ہر شخص کے لئے غذا کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی تھی.تا کہ تھوڑا کھانے والے بھی گذارہ کر سکیں اور زیادہ کھانے والے بھی اپنی خواہش کے مطابق کھا سکیں.(تاریـخ الیعقوبی ایام عمر بن الـخطاب) تاریخوںمیں ذکر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں جو فیصلے فرمائے ان میں دودھ پیتے بچوںکا خیال نہیں رکھا گیا تھا اور ان کو اس وقت غلّہ وغیرہ کی صورت میںمدد ملنی شروع ہوتی تھی جب مائیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیتی تھیں.ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے گشت لگا رہے تھے کہ ایک خیمہ میں سے کسی بچہ کے رونے کی آواز آئی.حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے.مگر بچہ تھا کہ روتا چلا جاتا تھا اور ماں اسے تھپکیاںدے رہی تھی کہ وہ سوجائے جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمہ کے اندر گئے اور عورت سے کہا کہ تم بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتیں یہ کتنی دیر سے رورہا ہے؟ اس عورت نے آپ کو پہنچانا نہیں.اس نے سمجھا کہ کوئی عام شخص ہے.چنانچہ اس نے جواب میں کہا کہ تمہیں معلوم نہیں.عمر نے فیصلہ کر ایا ہے کہ دودھ پینے والے بچہ کو غذا نہ ملے.ہم غریب ہیں ہمارا گذارہ تنگی سے ہوتا ہے میں نے اس بچے کا دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بیت المال سے اس کا غلّہ بھی مل سکے.اب اگریہ روتا ہے تو روئے عمر کی جان کو جس نے ایسا قانون بنایا
Page 300
ہے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت واپس آئے اور راستے میں نہایت غم سے کہتے جاتے تھے کہ عمر ! معلوم نہیں تو نے اس قانون سے کتنے عرب بچوں کا دودھ چھڑا کر آئندہ نسل کو کمزور کرایا ہے.ان سب کا گناہ اب تیرے ذمہ ہے.یہ کہتے ہوئے آپ سٹور میں آئے اور دروازہ کھولا اور ایک بوری آٹے کی اپنی پیٹھ پر اٹھا لی.کسی شخص نے کہا کہ لائیے میں اس بوری کو اٹھا لیتا ہوں.حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا.نہیں غلطی میری ہے اور اب ضروری ہے کہ اس کاخمیازہ بھی میں ہی بھگتوں.چنانچہ وہ بوری آٹے کی انہوں نے اس عورت کو پہنچائی اور دوسرے ہی دن حکم دے دیا کہ جس دن بچہ پیدا ہو اسی دن سے اس کے لئے غلّہ مقرر کیا جائے کیونکہ اس کی ماں جو اس کو دودھ پلاتی ہے زیادہ غذا کی محتاج ہوتی ہے.(تاریـخ ابن خلدون مترجم اردو جلد ۳ صفحہ ۳۶۴) اب دیکھو یہ انتظام اسلام نے شروع دن سے ہی کیا ہے گویہ نظام زیادہ دیر جاری نہیں رہا.مگرا س میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام ہیں ان میں یہی قانون پایا جاتا ہے کہ وہ کئی لہروں سے اپنی بلندی کو پہنچتے ہیں.ایک دفعہ وہ دنیا میں قائم ہو جاتے ہیں تو کچھ عرصہ کے بعد پرانے رسم ورواج کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں.مگر دماغوں میں ان کی یاد قائم رہ جاتی ہے اور ایک اچھا بیج دنیا میں بویاجاتاہے اور ہر شریف اور منصف مزاج انسان تسلیم کرتا ہے کہ وہ اچھی چیز تھی مجھے دوبارہ اس چیز کو دنیا میں واپس لانا چاہیے.پس گویہ نظام ایک دفعہ مٹ گیا مگر اب اسی نظام کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لئے احمدیت کا درخت لگایا گیا ہے اور وہ دن دور نہیں جب تمام دنیا اس کے شیریں اثمار کھا کر لذت حاصل کرے گی اور دنیا سے بھوک اور دکھ مٹ جائیں گے اور دنیا جنت کا نمونہ ہوگی.پھر اسلامی حکومت کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ دوسروں کے ملک پر طمع کی نظر نہ رکھے.چنانچہ فرمایا :.وَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا١ۙ۬ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ١ؕ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ( طٰہٰ:۱۳۲) یعنی اے مسلم تُو اپنی آنکھیں دنیاوی منافع کی طرف جو تمہارے سوا دوسری اقوام کو ہم نے دیئے ہیں اٹھا اٹھا کر نہ دیکھ اور تیرے رب نے جو تجھے دیا ہے وہی تیرے لئے اچھا ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے.یعنی مرنے کے بعد بھی وہی کام آئے گا اور جو دوسری اقوام پر تعدّی کر کے مال لو گے تو وہ نفع نہیں دے گا اور نہ قائم رہے گا.گویا اسلام آج کل کی حکومتوں کے طریق عمل کے خلاف اس بات سے روکتا ہے کہ یوں ہی دوسرے ممالک پر حملہ کرکے ان کو اپنے قبضہ میں لیا جائے.ہاں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت پر حملے ہوں یا حملوں کا خطرہ ہو تو اس کا دفاع کیا جائے ( الحج:۴۱،۴۲) نیز یہ حکم دیا گیا ہے کہ سرحدیں مضبوط رکھی جائیں (اٰل عـمران :۲۰۱)
Page 301
پھر اگر کوئی قوم حملہ کرے اور دفاع کے وقت مغلوب ہو جائے تو موجودہ حکومتوں کی طرح یہ اجازت نہیں دی گئی کہ مفتوحین سے عدل نہ کیا جائے اور ان کو معاف نہ کیا جائے بلکہ اسلامی حکومت کو یہی حکم ہے کہ وہ عدل سے کام لے.چنانچہ فرمایا :.يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ١ٞ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا١ؕ اِعْدِلُوْا١۫ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ١ٞ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ( المآئدۃ:۹) اے مومنو! اپنے تمام کاموں کو خدا کے لئے سر انجام دو اور انصاف سے دنیا میں معاملہ کرو اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس امر پر نہ اُکسا دے کہ تم عدل کا معاملہ نہ کرو تم بہر حال انصاف سے کام لو.یہ بات تقویٰ کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی ڈھال بنائو.اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے.پس اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ (۱) کسی ملک کو غصب کرنے کے لئے حملہ نہ کرو.(۲) اگر دفاعی جنگ کرنی پڑے.تب بھی دشمن کے مغلوب ہونے پر انصاف سے کام لو.پھر یہ حکم ہے کہ اگر دفاعی جنگ کرنی پڑے تو جب تک خون ریز جنگ نہ ہو کوئی قیدی نہ پکڑے جائیں.(الانفال:۶۸) اور جب خون ریز جنگ ہوجائے اور جنگی قیدی پکڑ لئے جائیں توان کے متعلق حسب ذیل احکام دیئے گئے ہیں.جنگی قیدیوں کے متعلق اسلام کے احکام ۱.یا تو ان قیدیوں کو احسان کر کے چھوڑ دیا جائے ( سورۂ محمدؐ) اوریہ ایسے قیدیوں کے متعلق ہی ہو سکتا ہے جو اپنی غلطی کا اقرار کریں اور آئندہ جنگ میں شامل نہ ہونے کا معاہدہ کریں.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قیدی ابو عزہ نامی کو رہا کیا.یہ شخص جنگ بدر میں پکڑا گیا تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ عہد لے کر چھوڑ دیا تھا کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شامل نہیں ہو گا.مگر وہ جنگ اُحد میں مسلمانوں کے خلاف پھر لڑنے کے لئے نکلا اور آخر حمراء الاسد کی جنگ میں مارا گیا.( شرح زرقانی، غزوۃ حمراء الاسد) ۲.اگر اسلامی حکومت کی مالی حالت ایسی نہ ہو کہ وہ احسان کر کے چھوڑ دے تو پھر قیدی کو حق ہے کہ وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے.لیکن اگر قیدی کو فدیہ کی طاقت نہ ہو تو پھر حکم ہے کہ اسلامی ملک کی زکوٰۃ میں سے اگر ممکن ہو تو اس کا فدیہ دے کر اس کو آزاد کردیا جائے.اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو قیدی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مکاتبت
Page 302
کرے یعنی حکومت سے یہ عہد کرے کہ وہ کمائی کر کے آہستہ آہستہ اپنا فدیہ دےدے گا اور اسے آزاد کر دیا جائے.چنانچہ وہ اس معاہدہ کے بعد فوراً آزاد ہو جائے گا اور قسط وار اپنا فدیہ اداکرے گا.یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پرانے زمانہ میں جنگیں افراد کرتے تھے اور اپنے اخراجات جنگ وہ خود برداشت کرتے تھے.اس لئے ان کا بوجھ اتارنے کے لئے دوسری قوم سے تاوان نہیں لیا جاتا تھا.بلکہ افراد پر حسب طاقت تاوان ڈالا جاتا تھا.اب چونکہ قومی جنگ ہوتی ہے اور حکومت خرچ کی ذمہ دار ہوتی ہے.لازماً اس نظام میں بھی موجودہ حالات کے لحاظ سے تبدیلی کرنی ہوگی.اور قیدی سے تاوان نہیں لیا جائے گا بلکہ حملہ آور قوم سے بحیثیت قوم تاوان لیا جائے گا.۳.جب تک تاوان جنگ ادا نہ کرے اس سے خدمت لی جاسکتی ہے.لیکن کام لینے کی صورت میں مندرجہ ذیل احکام اسلام دیتا ہے.(ا) تم کسی قیدی سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو.(ب) جو کچھ خود کھائو وہی قیدی کو کھلائو.اور جو کچھ خود پہنو وہی قیدی کو پہنائو.(ج) کسی قیدی کو مارا پیٹا نہ جائے.(د) اگر کوئی شادی کے قابل ہو.اور انہیں علم نہ ہو کہ کب تک وہ جنگی قیدی رہیں گے تو ان کی شادی کردو.یہ اصول نہایت ہی عادلانہ اور اعلیٰ درجہ کے ہیں.اس زمانہ میں حکومتیں متمدن سمجھی جاتی ہیں لیکن جنگی قیدیوں کے ساتھ ان کا سلوک اسلامی تعلیم کے مقابلہ میں بہت ہی ناقص ہے.مثلاً ان کے ہاں احسان سے چھوڑنا نہیں پایا جاتا.تاوان جنگ لینا مقدم سمجھا جاتا ہے.اسی طرح خوراک اور پوشاک کے معاملہ میں انہیں وہ کچھ کھلایا اور پہنایا نہیں جاتا جو خود آزاد لوگ کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں.پھر جنگی قیدیوں کی شادی کرانا تو کجا ان کی اپنی بیویوں کو بھی پاس آنے نہیں دیتے.الغرض اسلام کے پیش کردہ قوانین باقی تمام قوانین پر فضیلت رکھتے ہیں.پھر اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر جنگ ہو تو بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں اور مذہبی خدمت پر مامور لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے.اسی طرح مذہبی عبادت خانوں کی حفاظت کی جائے ( مسلم.طحاوی.ابو دائود ) نیز یہ بھی کہا ہے کہ مذہبی امور میں پوری آزادی ہونی چاہیے.کسی پر جبر نہ کیا جائے.پھر بار بار قرآن کریم میں معاہدات کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے.آج کل کی حکومتیں معاہدات تو کر لیتی ہیں
Page 303
لیکن خفیہ طور پر ان کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں.لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر معاہدہ ہو تو اس کی پابندی کرو.اور اگر خطرہ ہو کہ معاہد قوم شرارت کرے گی تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اچانک اس پر حملہ نہ کرو.بلکہ پہلے نوٹس دوکہ ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں.کیونکہ تمہاری طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے.اس کا اعلان کرنے کے بعد اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر بے شک جنگ کر سکتے ہو.یوں ہی نہیں.چنانچہ فرمایا:.وَ اِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآىِٕنِيْنَ۠ (الانفال:۵۹) کہ اگر کسی معاہد قوم کی طرف سے یہ خطرہ ہو کہ وہ معاہدہ کی پروا کئے بغیر حملہ کر کے خیانت کی مرتکب ہو گی.تو مساوات کا لحاظ رکھ کر ان کے عہد کو انہی کی طرف واپس پھینک دو.بےشک اللہ تعالیٰ دغابازوں اور معاہدہ توڑنے والوں کو دوست نہیں رکھتا.پھر فرمایا کہ اگر کوئی قوم صلح کرنا چاہے تو صلح کر لینا.یہ نہیں کہ ان کا ضرور مقابلہ کیا جائے.چنانچہ فرماتا ہے :.اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ (الانفال:۶۲) اے مسلم ! اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف جھکو اور اللہ کی مدد اور اس کی حفاظت پر بھروسہ رکھو.پھر اسلامی حکومت کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کسی قوم کو حقیر نہ سمجھا جائے.جیسے آج کل کی متمدن کہلانے والی حکومتیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فلاں کالے رنگ کے لوگ ہیں.اس لئے ان کے انسانیت کے کوئی حقوق نہیں اور ان کو ہم اپنا غلام سمجھتے ہیں.چنانچہ فرمایا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ (الحجرات:۱۲) کہ کوئی قوم دوسری قوم کو حقیر سمجھ کر اس کو پامال نہ کرے شاید وہ کل کو اس قوم سے اچھی ہو جائے.پھر چونکہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ساری دنیا میں ایک ہی نظام ہو.اس لئے قرآن کریم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اِنْ طَآىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا١ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ١ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوْا١ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ (الحجرات:۱۰) یعنی اگر دو قومیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کرا دو.یعنی دوسری قوموں کو چاہیے کہ بیچ میں پڑ کر ان کو جنگ سے روکیں اور جو جنگ کی وجہ ہو اس کو مٹائیں اور ہر ایک کو اس کا حق دلائیں.لیکن اگر باوجود اس کے ایک قوم باز نہ آئے اور مشترکہ انجمن کا فیصلہ نہ مانے.تو اس قوم سے جو زیادتی کرتی ہے سب دوسری قومیں مل کر لڑیں.یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی ظلم کا خیال چھوڑ دے.پس اگر وہ اس
Page 304
امر کی طرف مائل ہو جائے.توان دونوں قوموں میں صلح کرادو.مگرعدل سے اور انصاف سے کام لو.اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.ان آیات سے مندرجہ ذیل اصول مستنبط ہوتے ہیں :.۱.اگر دنیا میں کئی حکومتیں ہوں اور ان میں سے کسی دو حکومتوں میں اختلاف پیدا ہوجائے تو اسلامی اصول کی روشنی میں ان کا فرض ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایسی لیگ بنائیں جو ان دونوں میں صلح کرائے.۲.اگر صلح ہو جائے تو بہتر ورنہ باقی حکومتوں کی پنچائت مل کر ایک عادلانہ فیصلہ دے جس کو ماننے کے لئے مخالف حکومت کو مجبور کیا جائے.۳.اگر ایسے فیصلہ کو کوئی فریق نہ مانے یا ماننے کے بعد اس پر عمل کرنے سے انکار کر دے تو ساری طاقتیں مل کر اس سے لڑیں اور اسے مجبور کریں کہ وہ دنیا کے امن کی خاطر حکومتوں کی پنچائت کے فیصلہ کو تسلیم کرے.۴.جب اس پنچائتی دبائو یا لڑائی سے وہ حکومت صلح کی طرف مائل ہو جائے تو یہ حکومتوں کی پنچائت بغیر کسی ذاتی فائدہ اٹھانے کے صرف اس امر کے متعلق فیصلہ نافذ کرے جس سے جھگڑے کی ابتدا ہوئی تھی.اور مغلوب ہونے والی حکومت سے کوئی زائد فائدے اپنے لئے حاصل نہ کرے.کیونکہ اس سے نئے فسادات کی بنیادیں قائم ہوتی ہیں.یہ اصول ایسے زرّیں ہیں کہ ان اصولوں کی موجودگی میں دنیا کی جنگوں کے امکان بالکل کم ہو جاتے ہیں.اور دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے.پھر اسلام نے مذہبی آزادی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (البقرۃ:۲۵۷) دینی معاملات میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری آزادی ہونی چاہیے.جو شخص جبر سے دین میں داخل کیا جائے وہ بے شک ظاہراً تو جماعت میں داخل ہو سکتا ہے لیکن دل سے اس جماعت کے عقائد کا قائل نہیں ہوتا اور نہ دل سے ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اسلام چونکہ دلائل سے قائل کرنے اور قلوب کو فتح کرنے کا حکم دیتا ہے.اس لئے وہ لوگ جو دل سے اسلام کے قائل نہیں ہوتے اور دکھاوے کے لئے اسلام کو قبول کرتے ہیں ان کی برائی کو بیان کیا گیا ہے اور ان کو منافق کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے.پس اسلام مذہبی آزادی پر زور دیتا ہے اور بار بار یہ تعلیم دیتا ہے کہ اصل فتح دلائل کی فتح ہے نہ کہ اجسام کی فتح.
Page 305
خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کے پیش کردہ نظام حکومت اور کفار کے نظامِ حکومت میں زمین و آسمان کا فرق ہے.اوّل الذکر اگر قائم ہو جائے تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے اور ثانی الذکر دنیا کے امن کا ضامن نہیں ہو سکتا.اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جن فریقوں کے اصول میں اتنا بیّن فرق ہو وہ کبھی متحد فی العبادۃ نہیں ہوسکتے.تیسرے معنے دِیْن کے اَلسِّیْرَۃُ کے ہیں اور سِیْرَۃُ الاِنْسَانِ کی تشریح کرتے ہوئے لغت میں لکھا ہے کَیْفِیَّۃُ سُلُوْکِـــــہٖ بَیْنَ النَّاسِ.( اقرب ) یعنی انسا ن کی سیرۃ کے یہ معنے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے.اس مفہوم کے لحاظ سے آیت لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کی یہ تشریح ہو گی کہ اے منکرو! تمہارے لوگوں سے معاشرت کے طریق اور ہیں اور اسلام کے معاشرت کے طریق اور.اور یہ مسلمانوں اور ان کے مخالفوں کا ایک اہم اختلاف ہے.اس اختلاف کے ہوتے ہوئے کبھی دونوں فریق متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتے.اسلام کی رُو سے جو نیک سلوک دوسرے لوگوں سے کیا جائے وہ بھی عبادت کہلاتا ہے.چنانچہ حدیث میں آتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں ثواب کی نیت سے لقمہ ڈالے تو اس کا بھی خدا تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دے گا جیسا کہ صدقہ کا( بخاری کتاب الوصایا باب ان یترک ورثتہ اغنیاء.....) یعنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی عبادت سمجھا جائے گا.پس اسلام کی رُو سے بنی نوع انسان سے نیک سلوک بھی عبادت کا حصہ ہے اور جب اسلام کی تعلیم بنی نوع انسان سے نیک سلوک کرنے کے متعلق دوسروں سے مختلف ہے تو لازماً مسلمان اس قسم کی عبادت میں غیر مسلموں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا.کیونکہ وہ اسلامی حسن سلوک کے قائل نہیں.چوتھے معنے دین کے تدبیر کے ہیں اور لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کا مفہوم ان معنوں کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ اے منکرو ! ہمارا اور تمہارا اتحاد فی العبادۃ نہیں ہو سکتا.کیونکہ تمہاری تدبیر اور ہماری تدبیر میں بہت فرق ہے.تمہاری تدبیر اور رنگ کی ہے اور ہماری تدبیر اور رنگ کی.یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہر فرد کچھ نہ کچھ جدو جہد اور تدبیر کرتا ہے.کبھی اس لئے کہ وہ خدا تعالیٰ کو راضی کرے اور اس کی مشیت کو دنیا میں جاری کرے اور یہ تدبیر عبادت کہلاتی ہے.کیونکہ اس میں خدا تعالیٰ کی مشیت کو قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے تدبیر ہوتی ہے اور اس میں خود اپنا نفس اور خاندان بھی مدّ ِنظر ہوتا ہے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیں وَلِنَفْسِکَ عَلَیْکَ حَقٌّ.(بخاری کتاب الصوم باب من اقسم علی اخیہ) یعنی خدا تعالیٰ نے ایک مسلم پر بعض ذمہ داریاں اس کے اپنے نفس سے حسن سلوک کے لئے ڈالی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں بیوی سے حسن سلوک کے لئے بھی ڈالی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اپنے پڑوسی
Page 306
سے حسن سلوک کے لئے ڈالی ہیں.پس ایک مسلم خواہ بظاہر اپنے نفس سے سلوک کر ے یا اپنی بیوی سے سلوک کرے یا اپنے ہمسایہ سے حسن سلوک کرے وہ اسلامی تعلیم کے مطابق عبادت میں شامل ہے.اور ان امور میں غیرمسلموں کی تعلیم اور ہے اور اسلام کی تعلیم اور.اس لئے اگر یہ عبادت ہے تو لازماً غیر مسلموں کے ساتھ مسلم اس قسم کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا.پانچویں معنے دین کے مَا یُعْبَدُ بِہِ اللہُ کے ہیں.یعنی دین نام ہے ان تمام طریقوں کا جن کے ذریعے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے.مثلاً مسلمانوں میں نماز پڑھنا یا حج بیت اللہ کے لئے جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھا جاتا ہے.یہ طریق عبادت عربی زبان کے لحاظ سے دین کہلائے گا.ان معنوں کے اعتبار سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کی تفسیر یہ ہو گی کہ اے منکرو! تمہارے عبادت کے طریق اور ہیں اور میرے عبادت کے طریق اور ہیں.چونکہ اسلام کے سارے عبادت کے طریق پُر حکمت ہیں اور اس کے مقابلہ میں جو عبادات غیر مذاہب نے بتلائی ہیں وہ بغیر حکمت کے ہیں.اس لئے ایک مسلمان اپنے طریقوں کو چھوڑ کر ان کے طریق کو اختیار نہیں کرے گا اور غیر مذاہب والے چونکہ اسلام کو نہیں مانتے اس لئے وہ اسلامی طریق عبادت کو اختیار نہیں کریں گے.ایک مسلمان تو معقول طور پر ان کی عبادت میں شامل نہیں ہوگا اور دوسرے لوگ ضد اور مخاصمت کی وجہ سے مسلمانوں کی عبادت میں شریک نہیں ہوں گے پس مسلمانوں کی طرف سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کا اعلان صحیح اور درست ہے.چھٹے معنے دین کے اَلْمِلَّۃُ کے ہیں.اَلْمِلَّۃُ کے ایک معنے شریعت اور مذہب کے ہیں.اور دوسرے معنے قومیت، قومی نظام اور جماعت بندی کے ہیں.پس لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے معنے اس مفہوم کے اعتبار سے یہ ہوں گے کہ اے منکرو! تمہاری شریعت اور ہے اور میری شریعت اور.تمہاری جتھے بندی اور اصولوں پر مبنی ہے اور میرا قومی نظام اور اصولوں پر مبنی ہے.پس اس تفاوت کی بنا پر ہمارا تمہارا اجتماع فی العبادۃ نا ممکن ہے.اگر مِلَّۃ کے معنے شریعت اور مذہب کے لئے جائیں تو یہ امر واضح ہے کہ مشرکین کے پاس تو کوئی شریعت تھی ہی نہیں.سوائے چند رسم و رواج کی باتوں کے.اور وہ لوگ جو کسی مذہب کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان کے پاس جو کچھ شریعت کی باتیں ہیں.وہ اتنی نامکمل ہیں کہ انسانی زندگی میں پیش آمدہ مشکلات کا حل پوری طرح پیش نہیں کرتیں.لیکن اس کے خلاف اسلام کی پیش کردہ شریعت ایک مکمل شریعت ہے.اللہ تعالیٰ سورۂ مائدہ ع۱ میں
Page 307
فرماتا ہے :.اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.( المآئدۃ:۴) اے مسلمانو میں نے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنے احسان کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے.پس اسلام کا دعویٰ ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اس کی شریعت مکمل ہے اور جن امور کو دوسرے مذاہب نے چھؤا تک نہیں، اسلام نے ان کی جزئیات تک کو بیان کردیا ہے.اور ایک مسلمان کے لئے جن امور میں راہنمائی کی ضرورت پیش آسکتی ہے.ان سب کو مفصل طور پر واضح کر دیا اور ابدالآباد کے لئے اسے اور شرائع سے مستغنی کر دیا.الغرض ایک مسلم اپنی اعلیٰ شریعت کی موجودگی میں رسم و رواج کی باتوں پر چلنے والوں یا غیر مکمل اور ناقص تعلیم رکھنے والوں کے ساتھ عبادت میں کیونکر شامل ہو سکتا ہے اور اس کی ان کے پاس جا کر کیسے تسلّی ہو سکتی ہے.دوسرا حصہ ملّۃ کے لفظ کا قومیت اور جتھے بندی کے مفہوم پر مشتمل ہے.کسی ملک یا قوم کے افراد کے اندر خواہ کتنی ہی ذمہ داری کا احساس ہو جب تک کسی کام کو اجتماعی رنگ میں نہ کیا جائے اس وقت تک عظیم الشان نتائج نہیں پیدا ہو سکتے.اسلام نے اس نقطہ کو بار بار پیش کیا ہے اور امت محمدیہ کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہارا ایک ہاتھ پر جمع رہنا ضروری ہے.تاکہ تم اس مقصد اور ذمہ داری کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کی ہے اجتماعی رنگ میں کوشش کر سکو.ہماری نماز میں بھی اسی سبق کو دہرایا گیا ہے.چنانچہ جب تک ایک امام نہ ہو نماز نہیں ہوتی.اسی طرح اجتماعیت کی ہدایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :.وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰہِ جَمِیْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا.( اٰلِ عمران:۱۰۴) یعنی اے مسلمانو! خدا کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ ہی تم ایک ہاتھ پر جمع رہو اور تمہارے اندر تفرقہ پیدا نہ ہو بلکہ اجتماعی رنگ ہو.تا تمہاری کوششیں صحیح ثمر لا سکیں.پس اسلام نظام اور اجتماعی زندگی پر زور دیتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ یہ ہر حال میں قائم ہونی چاہیے.لیکن اس کے ساتھ ہی ارشاد فرماتا ہے :.تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ١۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ( المآئدۃ:۳) یعنی تمہاری اجتماعی کوششیں نیکی کے پھیلانے پر صرف ہونی چاہئیں اور اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو.اور گناہ اور ظلم اور بدی کے کاموں میں ہر گز کسی کی مدد نہ کی جائے.
Page 308
اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے متبعین اور دوسری قومیں اس بات کو ضروری نہیں سمجھتیں.اور نہ اس کو ملحوظ رکھتی ہیں.بلکہ اپنے ساتھی کے ساتھ خواہ وہ ظالم ہی ہو مل جاتی ہیں.اور اس کو غالب کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں.لیکن اسلام کی یہ تعلیم نہیں بلکہ وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہوں تعاون نہ کیا جائے.اور اگر کوئی ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روکا جائے.اور جو مظلوم ہو اس کی مدد کی جائے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :.اُنْصُـرْ اَخَاکَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ یَّا رَسُوْلَ اللّٰہِ اَنْصُـرُہٗ اِذَا کَانَ مَظْلُوْمًا اَفَرَءَیْتَ اِذَا کَانَ ظَالِمًا کَیْفَ اَنْصُـرُہٗ قَالَ تَـحْجُزُہٗ اَوْ تَـمْنَعُہٗ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذَالِکَ نَصْـرُہٗ.(بخاری کتاب الاکراہ باب یمین الرجل لصاحبہ) یعنی اے مسلم تیرا فرض ہے کہ تُو اپنے بھائی کی ہر حالت میں مددکر خواہ وہ ظالم ہویا مظلوم.ظالم ہونے کی صورت میں اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکا جائے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے اور مظلوم کی امداد کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کیا جائے.عام طور پر لوگ اس اصول پر نہیں چلتے.بلکہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں.لیکن اسلام کا یہ سنہرا اصل زرّیں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ نظام کے ساتھ ساتھ نیکی اور تقویٰ کے پھیلانے کے لئے کوششیں ہونی چاہئیں.جوتحریک نیکی پھیلانے کی ہو اس کے ساتھ تعاون ہو اور کوشش کی جائے کہ تمام لوگ اس میں شامل ہو جائیں.اور اگر کوئی تحریک نقصان رساں اور ضرر والی ہو تو قطعاً اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے.پس جن لوگوں کا نقطۂ نظر یہ ہو کہ جس بات میں کوئی فائدہ دیکھو اُدھر ہو جائو.خواہ اس میں دوسرے لوگوں پر ظلم ہی ہوتا ہو.ان کے ساتھ مسلمان کیونکر شامل ہوسکتے ہیں.ساتویں معنے اَلدِّیْن کے اَلْوَرَع کے ہیںاور آٹھویںمعنے اَلْمَعْصِیَۃُ کے ہیں.وَرَعَ کے معنے تقویٰ کے ہیںاور اَلْمَعْصِیَۃُ کے معنے ہوتے ہیں اطاعت سے نکلنا اور کسی امر کی خلاف ورزی کرنا.گویا وَرَعَ اور مَعْصِیَۃ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں.لیکن چونکہ اَلدِّیْن کے معنے جزا سزا کے بھی ہیں.اورجزا نیکی پر ملتی ہے اور سزا بدی پر.اس لئے دِیْنٌ کے معنے تفصیلی رنگ میں وَرَع اور مَعْصِیَۃ کے کر دیئے گئے ہیں.مذکورہ بالا معنوں کے اعتبار سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کا مفہوم یہ ہوگا کہ تمہارے لئے تمہار اطریق تقویٰ ہے اور میرے لئے میرا طریق تقویٰ ہے.یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہوں اور تم خدا تعالیٰ کی توحید کے منکر
Page 309
ہو اور بتوں سے ڈرتے ہو.اس لئے جبکہ دونوں کا ڈر مختلف ہستیوں سے ہے اور دونوں کی امید مختلف ہستیوں سے ہے تو ہماری اجتماعی عبادت اکٹھی کس طرح ہو سکتی ہے.تم اپنے اعمال میں بتوں کی خوشنودی مدّ ِنظر رکھو گے.یعنی جو تمہارے باپ دادا نے ڈھکونسلے بنا رکھے ہیں کہ بتوں سے ان ان باتوں میں ڈرناچاہیے اوران ان باتوںمیں ان سے امید رکھنی چاہیے.تم اس کی پیروی کرو گے اور میں اپنے تمام اعمال میں اس امر کو مدّ ِنظر رکھوں گا کہ الٰہی کلا م کے مطابق کن کن باتوں سے خدا تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور کن کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے.پس تمہارا اور میرا اتحاد فی العبادۃ کس طرح ہو سکتا ہے.نویں معنے اَلدِّیْن کے اَلْـحَال کے ہیں اس مفہوم کے اعتبار سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے یہ معنے ہوں گے کہ تمہاری حالت اور ہے اور میری حالت اور.یعنی میرے روز مرہ کے کام اور اصول پر سرانجا م رہے ہیں اور تمہارے روزمرہ کے کام اور اصول پر ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لَمْ یُبْدَأْ بِبِسْمِ اللہِ فَھُوَ اَبْتَرُ.یعنی ہر کام جو اللہ کا نام لے کر نہ شروع کیا جائے وہ بے نتیجہ ہوتاہے.گویا ہر کام میں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے.خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا کیونکہ اس کی مدد کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں چل سکتا.اور اگر اس کی مددشامل حال ہو تو ایک کمزور آدمی بھی بہت کچھ کر جاتاہے.پھر بسم اللہ کا حکم ہر کام سے پہلے دے کر گویا ایک مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی ہر حرکت خدا تعالیٰ کے لئے ہونی چاہیے.کیونکہ برے کام سے پہلے تو کوئی بھی بِسْمِ اللّٰهِ نہیں پڑھے گا.لازماً بِسْمِ اللّٰهِ ایسے ہی کام کے متعلق پڑھی جائے گی جس میں اللہ کی ذات بندہ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے.پس اس حکم کے ذریعہ سے ان تمام بدیوں کی جن کے لوگ مرتکب ہوتے ہیں روک تھام ہو جائے گی.جب کوئی مسلمان بِسْمِ اللّٰهِ پڑھے گا اور اس کا برا ارادہ ہوگا تو فوراً اسے یاد آجائے گا کہ اس کو تو خدا تعالیٰ نے اس کا م سے روکا ہو اہے.اس لئے وہ لازماً اس سے رُک جائے گا اور ناجائز کاموں کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا.پھر بنی نوع انسا ن کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے عفو اور رحم کو مدّ ِنظر رکھے گا.کیونکہ اللہ کی صفات رحمٰن اور رحیم اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ بندے بھی اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لئے دعائیں سکھلائی ہیں.ان سے ایک طرف تو انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے اور وہ دست درکار و دل بایار کا مصداق ہو جاتا ہے.دوسرے اس میں یہ حکمت ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو.کیونکہ اگر وہ کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم
Page 310
کے خلاف کر رہا ہوگا تو وہ دعانہیں کر سکے گا.پس ایک مسلم کے روزمرہ کے اصول جن پر اس کے کام سرانجام پارہے ہیں وہ اور ہیں اور دوسرے مذاہب والوں کے اور.غیر مذاہب والے نہ جائز طریقوں کو دیکھتے ہیں نہ ناجائز کو.ان کی ساری توجہ اسی طرف ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ان کا مقصد حاصل ہو خواہ کسی ذریعہ سے ہو.اور خواہ اس ضمن میں ہزاروں لوگوں کی جانیں تلف ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے.لیکن اسلام اس بات سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِہٖ وَیَدِہٖ.(بخاری کتاب الایـمان باب المسلم من سلم المسلمون....)کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہیں اور ان کو کسی قسم کا دکھ نہ پہنچے.پس مسلمان اپنے روزمرہ کے کام اس نقطہ کو مدّ ِنظر رکھ کر کر رہا ہے کہ کسی کو دکھ نہ پہنچے اس کے مقابل پر کافر نہ اس کا دھیان رکھتا ہے اور نہ اس چیز کو کوئی اہمیت دیتاہے.پس ان حالات میں مسلمانوں کا لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کہنا بالکل برمحل ہوگا.دسویں معنے اَلدِّیْن کے اَلشَّاْنُ کے ہیں.اور اَلشَّاْنُ کے معنے لغت میں اَلْـخَطْبُ الْعَظِیْمُ کے لکھے ہیں.( اقرب) یعنی اہم کام، بہت بڑی مہم.اس مفہوم کے اعتبار سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے معنے یہ ہوں گے کہ اے منکرو! تمہارے لئے بھی تمہارا ایک اہم مقصد ہے اور میرے لئے بھی میرا ایک اہم مقصد ہے.تمہارے مدّ ِنظر بھی ایک سکیم او رمہم ہے اور میرے مدّ ِنظر بھی ایک سکیم اور مہم ہے اور ہر دو سکیموں اور مقصدوں میں بہت بڑا فرق ہے.اس لئے ہمارا اجتماع ناممکن ہے.کافروں کا اہم مقصد کیا ہے؟ صرف یہ کہ لوگ رسم ورواج کے پیچھے چلیں.لیکن قرآن کریم اس بات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رسم ورواج کچھ چیز نہیں بلکہ رسم و رواج کی تقلید ایک جہالت کی بات ہے.اس کے مقابل پر مسلمانوں کا اہم مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا پر توحید پھیل جائے اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت زمین پر پوری طرح قائم ہو جائے.اس کی نازل کردہ شریعت پر تمام لوگ چل پڑیں اور مشرق ومغرب اور شمال و جنوب کے رہنے والے سب کے سب ایک ہی نقطۂ مرکزی پر جمع ہوجائیں.ایک ہی معبود ہو اور ایک ہی رسول ہو اور ایک ہی شریعت.اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر لے لیں.تادنیا جنگوں کی لپیٹ سے نکل کر امن کا گہوارہ بن جائے اور صرف ذاتی فوائد، خاندانی عزت اور قومی اور ملکی کوششوں کو ترک کر کے عالمگیر فوائد کے لئے سب انسان مل کر کوشش کریں اور ایک طرف ان کا اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق ہو اور دوسری طرف بنی نوع انسان کے حقوق پوری طرح ادا ہوں.
Page 311
یہودیت، عیسائیت او ردیگر مذاہب ایک ایک قوم کے لئے ہیں.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لئے مبعوث کئے گئے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ.(سبا:۲۹ ) اے ہمارے رسول ہم نے تجھے ساری دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :.اُعْطِیْتُ خَمْساً لَمْ یُعْطَھُنَّ اَحَدٌ قَبْلِیْ نُصِـرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیْرَۃَ شَھْرٍ وَجُعِلَتْ لِیَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَھُوْرًا وَّ اُحِلَّتْ لِیَ الْغَنَآئِمُ وَاُعْطِیْتُ الشَّفَاعَۃَ وَکَانَ النَّبِيُّ یُبْعَثُ اِلٰی قَوْمِہٖ خَاصَۃً وَّبُعِثْتُ اِلَی النَّاسِ عَامَّۃً ( بخاری کتاب الـتیمم باب التیمم )وَّ فِیْ روَایَۃٍ بُعِثْتُ اِلَی الْاَحْـمَرِ وَالْاَسْوَدِ.(مسند احـمد مسند عبد اللہ بن عباس) یعنی مجھے پانچ ایسی خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں.مجھے ایک ماہ کی مسافت تک خدا داد رعب عطا کیا گیا ہے.(۲) میرے لئے تمام زمین مسجد او رطہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے.(۳) میرے لئے جنگوں میں حاصل شدہ مال غنیمت جائز قرار دیا گیا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ جو اموال دشمن کے ان کے ہاتھ آئیں.ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے مگر مجھے اجازت دی گئی ہے کہ خواہ میں ان اموال کو اپنے ان فوجیوں میں تقسیم کر دوں جو بغیر کسی تنخواہ کے دفاع ملک کے لئے لڑتے ہیں اور خواہ دشمن کو مال لَوٹا دوں.(۴) مجھے شفاعت کا مقام عطا کیا گیا ہے.(۵) مجھ سے پہلے ہرنبی اپنی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا.مگر مجھے سب بنی نوع انسان کے لئے مبعوث کیا گیا ہے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میں اسود و احمر یعنی سیاہ و سفید سب کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں.پس محمدی سکیم یہ ہے کہ ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور متفرق لوگوں کو جو دنیا کے خواہ کسی کونے میں رہتے ہوں.خدائے واحد کے آستانہ پر لاکھڑا کیاجائے تا سب کا ایک نقطۂ نگاہ ہو اور ایک ہی مقصد ہو تاسب دنیا مساوی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں.لَیْسَ لِلْعَرَبِیِّ عَلَی الْعَجَمِيِّ فَضْلٌ یعنی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے کہ سب قومیں جو عرب کے سواہیں ان کا بھی معیار اونچا کیا جائے تا عربی اور عجمی سب ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں.پس مسلمانوں کی سکیم سب دنیا کو بہترین پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی ہے.
Page 312
اس کے مقابل منکرین اسلام کی سکیم محض رسم و رواج کی ترویج یا ایک قوم اور خاندان کے لئے فائدہ حاصل کرنے کی جد وجہد ہے.پس ان حالات میں جبکہ دونوں فریقوں کا مقصود علیحدہ علیحدہ ہے.کیوں کر اجتماع فی العبادۃ ہو سکتا ہے.گیارہویں معنے دِیْن کے اَلْعَادَۃُ کے ہیں.عادت اور سیرت درحقیقت ایک ہی مفہوم رکھتی ہیں.فرق صرف یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی کام اس لئے کرتا ہے کہ اس کے اندر سے ایک رو پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات کوئی کام بیرونی اثرات کے ماتحت کیا جاتا ہے.پس جو کام تو اندرونی شعور کے ماتحت کیا جائے وہ سیرت کہلاتا ہے اور جو بیرونی اثرات کے ماتحت کیا جائے وہ عادت کہلاتا ہے.دِیْن کے ان معنوں کے لحاظ سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِکا یہ مفہوم ہو گا کہ اے منکرو! تمہارے لئے تمہاری عادات ہیں اور میرے لئے میری عادات.یعنی تمہاری عادات میری عادات سے بالکل مختلف ہیں.تمہاری عادات اپنے باپ دادا کی تقلید کے ماتحت ہیں.جنہوں نے کسی عقلی وجہ پر اپنے لئے قانون نہیں بنایا تھا.لیکن میری عادات ان احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوئی ہیں جو حکیم خدا کی طرف سے زبردست حکمتوں کے ماتحت نازل ہوئے ہیں.تم رسم و رواج کے بندے ہو.جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا.اس کو اپنا لیا اور عادت بنا لیا خواہ وہ عادات صریح طور پر تباہی کی طرف لے جانے والی ہوں.اس کے مقابل پر میری عادات کا منبع اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں.اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے صِبْغَۃَ اللّٰہِ (البقرۃ:۱۳۹) یعنی تم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو.سو میں نے اپنی عادات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ماتحت ڈھالا ہے اور وہ عادات اس فطرت صحیحہ کے مطابق ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فِطْرَتَ اللّٰہِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا ( الرّوم:۳۱) یعنی انسان فطرت صحیحہ پر پیدا کیا گیا ہے اور پھر اسلام کے صحیح ماحول میں رہنے کی وجہ سے اس کی فطرت صحیح طور پر نشو نما پاتی ہے اور الٰہی تعلیم کا پانی جب اسے دیا جاتا ہے تو وہ بہترین نشو نما پا کر بہترین پھل لاتا ہے جس سے اس کے اپنے رشتہ دار و اقارب اور دیگر لوگ پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور وہ بہترین سوسائٹی کا ایک بہترین فرد ہوتا ہے.لیکن تمہارے ہاں پیدا ہونے والا بچہ آتا تو بہترین فطرت کے ساتھ ہے مگر اَبَواہُ یُـھَوِّدَانِہٖ اَوْ یُـمَجِّسَا نِہٖ اَوْ یُنَصِّـرَانِہٖ.(الطبرانی فی الجامع الکبیر بـحوالہ جامع الصغیر حرف الکاف) اگر وہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو ان میں رائج شدہ عادات کو لے لیتا ہے اور اگر وہ مجوسیو ں کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو ان کی عادات کا عادی ہو جاتا ہے اور اگر وہ نصاریٰ کے ہاں جنم لیتا اور پرورش پاتاہے تو ان کی عادات کا
Page 313
حامل ہو جاتا ہے.گویا اس کا مذہب اس کے باپ دادا کا مذہب ہوتا ہے وہ اپنے ماحول کا اثر لے لیتا ہے مشرک کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اپنے مشرک والدین کے اثر کے ماتحت بتوں کو پوجنے لگتا ہے اور رسم و رواج کی تقلید کرنے لگتا ہے.پس تمہاری عادات اور ہیں اور میری عادات اور.عادات کا اتفاق بھی فریقین کے لئے ملنے کا ایک سبب اور وجہ بن جا یا کرتا ہے لیکن یہاں یہ وجہ بھی نہیں پائی جاتی.پس تمہارا راستہ اور ہے اور میرا راستہ اور.اس لئے ہم کسی طرح متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتے.اور ہماری طرف سے لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کا اعلان ایک کھلی حقیقت ہے.اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو محض عناد اور بُغض کی بنا پر کی گئی ہو.خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ کافرون میں جو مسلمانوں کو کفار سے عبادت میں انقطاع کلّی کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی مکمل وجوہات لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے فقرہ میں بتائی گئی ہیں.ہم بتا چکے ہیں کہ اسلام کی رو سے محض نماز کا نام عبادت نہیں.بلکہ تمام اخلاقی اور روحانی کا م خواہ تمدن سے تعلق رکھتے ہوں یا سیاست سے یا معیشت سے.جب وہ خدا تعالیٰ کی خاطر کئے جائیں اور روحانی ترقی کے لئے کئے جائیں تو وہ بھی عبادت ہی ہوتے ہیں.پس یہ جو اس سورۃ میں فرمایا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر عبادت نہیں کر سکتا.اس میں وہ تمام امور شامل ہیں جو معیشت، سیاست یا تمدن سے تعلق رکھتے ہیں.ان سب امور میں اسلام نے محبت، پیار، انصاف، نظم اور خدا تعالیٰ کی رضا مندی کو مدّ ِنظر رکھ کر احکام دیئے ہیں.لیکن دوسرے مذاہب نے یا تو صرف جبری احکام دیئے ہیں یا باپ دادا کی رسم و رواج کی تقلید کی ہے اور کروانی چاہی ہے.اس لئے عبادت یعنی خواہ وہ ایسی عبادت ہو جو نماز کا رنگ رکھتی ہے.یا ایسی عبادت ہو جو معیشت یا تمدن یا سیاست پر مشتمل ہو لیکن ہو خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے.اس میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کا اتحاد نا ممکن ہے.کیونکہ دونوں کے اصول احکام ایک دوسرے سے بالکل متبائن ہیں.الغرض قرآن کریم نے سب سے پہلے ایک حکم دیا کہ ہر مسلمان کو یہ کھلم کھلا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ کافروں کے ساتھ کسی طرح متحد فی العبادۃ نہیں ہو سکتا پھر اس اعلان کی وجوہات لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے الفاظ میں بیان کردیں.لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کے الفاظ کتنے مختصر ہیں لیکن اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے.اگر اس مفہوم کو پوری تفصیلات کے ساتھ قلم بند کیا جائے تو اس سے ایک خاصے حجم کی کتاب تالیف ہو سکتی
Page 314
ہے درحقیقت یہ صرف عربی زبان کی ہی خوبی ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے ایک لفظ کے ساتھ اتنے بڑے مضمون کو بیان کر جاتی ہے جو دوسری زبانوں میں پوری کتاب لکھنے سے بھی مکمل نہیں ہوتا.اور یہ بات عربی کے اُمّ الالسنہ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے.خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سبق سکھا یا ہے کہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی شریعت ہر طرح سے اکمل اور اعلیٰ ہے.ان کے عبادت کے طریق دوسرے مذاہب کی عبادت کے طریقوں سے افضل ہیں.ان کا معاشرہ اعلیٰ درجہ کا ہے.ان کے حکومت کے اصول بہترین ہیں.ان کا نظام جماعت نہایت عمدہ ہے اور ان کا مقصد حیات نہایت ہی مبارک ہے.پس ان باتوں کے حامل شخص کا فرض ہے کہ وہ ہر موقعہ پر کفر کے سامنے ڈٹ جائے اور اسلام کی فضیلت کو ثابت کرے اور کبھی کسی رنگ میں بھی کفر سے مرعوب اور متاثر نہ ہو.کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی اور اسے کبھی بھی کامل نظام حاصل نہیں ہو گا پس مسلمان کا اس معاملے میں دوسروں سے علیحدہ ہونا ضد کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ بنی نوع انسان کی خیر خواہی اور ترقی کے لئے ہو گا.اس کے مقابلے میں دشمنوں کا ایسے پاکیزہ نظام سے الگ ہونا یا تو ضد کی وجہ سے ہو گا یا بنی نوع انسان کی ترقی سے آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے ہو گا.
Page 315
سُوْرَۃُ النَّصْـرِ مَدَنِیَّۃٌ سورۃ نصر.یہ سورۃ مدنی ہے وَھِیَ اَرْبَعُ اٰیَاتٍ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ اور بسم اللہ کو شامل کر کے اس کی چار آیات ہیں سورۃ نصر مدنی ہے سورۃ نصر مدنی سورۃ ہے اور اس کے متعلق کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا.سب مفسرین کا اس کے مدنی ہونے پر اتفاق ہے.( فتح البیان سورۃ النصر ) ہاں وقتِ نزول کے متعلق تین روایات تفاسیر میں بیان ہوئی ہیں.سورۃ نصر کے وقت نزول کے متعلق مختلف روایات پہلی روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ اِنَّ نُزُوْلَھَا عِنْدَ مُنْصَـرَفِہٖ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مِنْ خَیْبَرَ.( روح المعانی سورۃ النصر) کہ سورۃ نصر اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لارہے تھے.اور غزوہ خیبر ۷ ھ میں ہوئی ہے.گویا اس روایت کے لحاظ سے سورۃ نصر کانزول ۷ ھ میں ہوا ہے.دوسری روایت سورۃ نصر کے نزول کے متعلق یہ آتی ہے کہ ابن عباسؓ کہتے ہیں لَمَّا اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَۃِ حُنَیْنٍ اَنْزَلَ اللہُ عَلَیہِ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ.( در منثور سورۃ النصر) یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے اس وقت سورۃ نصر نازل ہوئی.فتح مکہ رمضان ۸ ھ میں ہوئی ہے اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں شامل ہوئے.کیونکہ فتح مکہ کے بعد ابھی آپؐمکہ میں ہی قیام فرما تھے کہ آپؐکو معلوم ہواثقیف اور ہوازن کے قبیلے فساد پر تُلے ہوئے ہیں.چنانچہ خبر ملتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کی طرف روانہ ہوئے اور حنین کے مقام پر ان سے مقابلہ ہوا.پہلے تو مسلمانوں کے پائوں اُکھڑ گئے.لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مد دسے مسلمانوں کو فتح ہو گئی.اور مسلمان فاتحانہ شان سے واپس ہوئے.حضرت ابن عباس ؓ کا قول ہے کہ سورۃ نصر کے نزول کا وقت جنگِ حنین سے واپسی کا ہے گویا اس لحاظ سے اس سورۃ کا نزول ۸ ھـ میں ماننا پڑے گا.
Page 316
تیسری روایت اس سورۃ کے نزول کے متعلق یہ آتی ہے کہ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ قَالَ ھٰذِہِ السُّوْرَۃُ نَزَلَتْ عَلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَوْسَطَ اَیَّامِ التَّشْـرِیْقِ بِـمِنیً وَھُوَ فِیْ حَـجَّۃِ الْوَدَاعِ.( در منثور سورۃ النّصر) یعنی حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقعہ پر مِنٰی کے میدان میں نازل ہوئی.( فتح البیان ) اور اس سورۃ کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسّی دن زندہ رہے اور بعض کہتے ہیں کہ ستر دن زندہ رہے.ان سب روایات پر غور کرنے سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سورۃ کا حجۃ الوداع کے موقعہ پر نازل ہونا ہی درست ہے.کیونکہ دوسری روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں.چنانچہ درمنثور میں یہ روایت آتی ہے کہ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نُعِیَتْ اِلَیَّ نَفْسِیْ اَنِّیْ مَقْبُوْضٌ فِیْ تِلْکَ السَّنَۃِ.( در منثور سورۃ النّصر) یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ میرا کام اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کر نا اور اسلام کو پھیلانا تھا اور اب جوق در جوق لو گ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے ہیں اور اسلام دنیا میں پھیل گیا ہے اس لئے جتنا کام خدا تعالیٰ نے لینا تھا وہ لے لیا ہے اور آپؐ اب خدا تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں اور آپؐکی وفات کا وقت قریب ہے.پھر آپؐکو خدا تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپؐاسی سال وفات پاکر اللہ تعالیٰ کے حضورپہنچ جائیں گے.مذکورہ بالا روایت سے یہ امر واضح ہوجاتا ہے کہ اگر سورۃ نصر ۷ھ یا ۸ ھ میں نازل شدہ ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اَنِّیْ مَقْبُوْضٌ فِیْ تِلْکَ السَّنَۃِ یعنی میں اس سال وفات پا جائوں گا کبھی بھی واقعات سے تطابق نہ پاسکتا.کیونکہ آپؐکی وفات ۱۱ ھ میں ہوئی ہے اور ۷،۸ھ میں اور ۱۱ ھ میں تین چار سال کا فرق ہے نہ کہ ایک سال کا.آپؐکے یہ الفاظ واقعات کے لحاظ سے تبھی درست ہوسکتے ہیں جبکہ آپؐنے یہ الفاظ ۱۰ھ میں فرمائے ہوں.گویا حسابی لحاظ سے بھی حجۃ الوداع کا موقعہ ہی صحیح قرار پاتا ہے جب کہ یہ سورۃ نازل ہوئی.پس اس سورۃ کے حجۃ الوداع کے موقعہ پر نازل ہونے کی روایت ہی درست معلوم ہوتی ہے.اس روایت سے یہ بھی ظاہرہوتا ہے کہ ابن عباسؓ کی طرف منسوب شدہ پہلی روایت جس میں اس سورۃ کا جنگِ حنین سے واپسی پر نازل ہونا قرار دیا گیا ہے درست نہیں.کیونکہ ایک ہی شخص کے دوبیان بیک وقت نہیں ہو سکتے.دوسری روایت جو اس بات کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ سورۃ نصر حجۃ الوداع کے موقعہ پر ہی نازل ہوئی تھی یہ ہے کہ
Page 317
اَنَّـھَا لَمَّا نَزَلَتْ خَطَبَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ عَبْداً خَیَّرَہُ اللہُ بَیْنَ الدُّنْیَا وَبَیْنَ لِقَآئِہٖ فَاخْتَارَ لِقَآءَ اللہِ فَعَلِمَ اَبُوْ بَکْرٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ فَقَالَ فَدَیْنَاکَ بِاَنْفُسِنَا وَاَمْوَالِنَا وَاٰبَائِنَا وَاَوْلَادِنَا.(روح البیان سورۃ النصر) یعنی جب سورۃ نصرنازل ہوئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور تمثیلاً یہ بتایا کہ اب آپؐکی وفات کا وقت قریب ہے.چنانچہ آپؐنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا میں رہے اور خواہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے.تو اس بندے نے خدا تعالیٰ کے پاس جانے کو ترجیح دی.حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس تمثیل کو سمجھ گئے اور بے تاب ہو کر کہنے لگے.یارسول اللہ آپ پر ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ اور بیوی بچے سب قربان ہوں.آپؐکے لئے ہم اپنے اموال اور دوسری سب چیزیں قربان کر نے کے لئے تیار ہیں.گویا جس طرح کسی عزیز کے بیمار ہونے پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اور سب عزیزوں کی قربانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پیش کی اور خواہش کی کہ کاش حضور جیتے رہیں اور ہماری قربانی قبول کر لی جائے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کا ذکر بخاری میں بھی آتا ہے.لیکن ان مذکورہ بالا الفاظ سے اس کے الفاظ کا قدرے اختلاف ہے.بخاری میں بیان شدہ خطبہ کے الفاظ یہ ہیں :.اِنَّ اللہَ خَیَّرَ عَبْدًا بَیْنَ الدُّنْیَا وَبَیْنَ مَا عِنْدَہٗ فَاخْتَارَ ذٰلِکَ الْعَبْدُ مَا عِنْدَ اللہِ.قَالَ: فَبَکٰی اَبُوْبَکْرٍ فَعَجِبْنَا لِبُکَآئِہٖ اَنْ یُّـخْبِرَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خُیِّرَ.فَکَانَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ھُوَ الْمُخَیَّرَ.وَکَانَ اَبُوْبَکْرٍ اَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَمَنَّ النَّاسِ عَلَیَّ فِیْ صُـحْبَتِہٖ وَمَالِہٖ اَ بُوْبَکْرٍ وَلَوْ کُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِیْلًا غَیْرَرَبِّیْ لَاتَّـخَذْتُ اَبَا بَکْرٍ خَلِیْلًا وَلٰکِنْ اُخُوَّۃُ الْاِسْلَامِ وَمَوَدَّتُہٗ لَا یَبْقَیَنَّ فِیْ الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلَّا سُدَّ اِلَّا بَابَ اَبِیْ بَکْرٍ.( بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قَوْلِ النَّبِیِّ سُدُّوا الْاَبْوَابَ اِلَّا بَابَ اَبِیْ بَکْرٍ) یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اپنی رفاقت اور دنیوی ترقیات میں سے ایک کے انتخاب کی اجازت دی اور اس نے خدا تعالیٰ کی رفاقت کو ترجیح دی.دوسرے صحابہ تو اس تمثیل کو نہ سمجھ سکے.لیکن حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئیں.صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے بندے کا ذکر فرما رہے ہیں جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ وہ اس دنیا میں رہے اور فتوحات سے لذت اٹھائے اور خواہ اللہ تعالیٰ کے پاس آجائے.بھلا یہ کون سا رونے کا مقام ہے کیونکہ اسلام کی فتوحات کا وعدہ پیش کیا جارہا ہے.راوی بیان کرتا ہے کہ
Page 318
درحقیقت صحابہ کا قیاس درست نہ تھا بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خداداد فراست سے جو بات معلوم کر لی وہی درست تھی کہ یہ تمثیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے اور یہ کہ آپؐہی وہ شخص ہیں جن کو اختیار دیا گیا تھا اور آپؐنے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو پسند فرمایا.حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رونا برمحل تھا.جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بے تابی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا توآپ کی تسلی کے لئے فرمایا.ابو بکر ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سبقت قدمی کرتے ہوئے اپنے مال اور اپنی جان سے میری خدمت کی ہے اور اپنی قربانی کی وجہ سے یہ مجھے اتنے محبوب ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو محبت کا انتہائی مقام دینا جائز ہوتا تو میں ان کو دیتا.مگر اب بھی یہ میرے دوست اور صحابی ہیں اور اسلامی رشتہ اور اسلام کی پیدا کردہ محبت ہمیں ملائے ہوئے ہے.پھر فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے سب لوگوں کی کھڑکیاں جو مسجد میں کھلتی ہیں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے اور اس طرح آپ کے عشق کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داد دی.کیونکہ یہ عشق کامل ہی تھا جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ اس فتح و نصرت کی خبر کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے.اور تبھی آپ نے بے اختیار ہو کر کہہ دیا فَدَیْنَاکَ بِاَنْفُسِنَا وَاَمْوَالِنَا وَاٰبَائِنَا وَاَوْلَادِنَا کہ اے کاش ہماری اور ہمارے عزیزوں کی جانوں کو قبول کرلیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہیں.بخاری کی شرح ارشاد الباری میں اس حدیث کے ماتحت لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ اپنی وفات سے تین دن قبل دیا تھا.گویا یہ خطبہ آخری وقت کا ہے اور اس خطبہ کی بناسورۃ نصر تھی.پس سورۃ نصر کا نزول بھی وفات کے عرصہ کے قریب ہی ماننا پڑے گا وگرنہ یہ تو قیاس میں نہیں آسکتا کہ سورۃ نصر ۷، ۸ھ میں نازل ہو.اور آپؐکو علم ہو جائے کہ اب میری وفات قریب ہے لیکن خطبہ تین چار سال بعد دیا جائے.اوروفات بھی تین چار سال بعد واقع ہو.پس مذکورہ بالا روایت کی موجودگی میں یہ واضح ہوجاتا ہے کہ سورۃ نصر وفات کے قریبی عرصہ میں نازل ہوئی تھی اور روایات کے مطابق وہ حجۃ الوداع کا موقع ہی بنتا ہے.گویا حج کے موقعہ پر سورۃ نصر نازل ہوئی اور حضورؐ نے یہ بات سمجھ لی کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے.اور وحی نے بھی اس کو متعین کر دیا.سو مدینہ پہنچ کر حضورؐنے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دے دی اور چند ہی دنوں بعد داغِ مفارقت دے کر اللہ تعالیٰ کے حضورچلے گئے.تفاسیر میں بعض اور روایات بھی آتی ہیں جو مذکورہ بالا بیان کی تصدیق کرتی ہیں.چنانچہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے.قَالَ عَلِیٌّ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ لَمَّا نَزَلَتْ ھٰذِہِ السُّوْرَۃُ مَرِضَ رَسُوْلُ اللّٰہِ عَلَیْہِ السَّلَامُ فَـخَرَجَ اِلَی النَّاسِ فَـخَطَبَـھُمْ وَوَدَّعَھُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْمَنْزِلَ فَتُوَفِّیَ بَعْدَ اَیَّامٍ.یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
Page 319
جب سورۃ نصر نازل ہوئی تو اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا حملہ ہوا اور اس بیماری کے دوران میں آپؐگھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ ؓ کے مجمع میں ایک تقریر فرمائی اور اپنی موت کی خبر دے کر ان کو الوداع کہا پھر گھرتشریف لے گئے اور اس واقعہ کے چند ہی دنوں بعد آپؐکیوفات ہو گئی.اس روایت سے بھی ہمارے اوپر کے بیان کی پوری تصدیق ہوتی ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایا م میں نازل شدہ ہے.سورۃ نصر کے وقت نزول کی تعیین میں مفسرین کی لغزش ہمارے اکثر مفسر ایسے ہیں جنہوں نے اس واضح حقیقت کو چھوڑ کر محض ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہوئے سورۃ نصر کو ۸ھ یا اس سے قبل کی نازل شدہ قرار دینے کی کوشش کی ہے.چنانچہ تفسیر رازی میںلکھا ہے.اَلْاَصَـحُّ ھُوَ اَنَّ السُّوْرَۃَ نَزَلَتْ قَبْلَ فَتْحِ مَکَّۃَ.کہ صحیح بات یہ ہے کہ سورۃ نصر فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی.اسی طرح تفسیر روح البیان میں لکھا ہے.اِنَّ السُّوْرَۃَ نَزَلَتْ قَبْلَ فَتْحِ مَکَّۃَ کَمَا عَلَیہِ الْاَکْثَـرُ کہ یہ سورۃ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی جیسا کہ اکثر مفسرین کی رائے ہے.یہ مفسرین جنہوں نے سورۃ نصر کے نزول کے متعلق ان روایات کو ترجیح دی ہے جن میں اس کے نزول کو فتح مکہ سے قبل بتایا گیا ہے.یہ کسی چھان بین کے نتیجہ میں نہیں یعنی وہ تفتیش اور بحث و تمحیص کے بعد اس نتیجہ پر نہیں پہنچے کہ یہ روایات درست ہیں اور دوسری غلط ہیں.بلکہ اس کی وجہ درحقیقت ان کی ایک مشکل تھی جس کو وہ حل نہ کرسکے.اور مجبور ہوگئے کہ اس سورۃ کو فتح مکہ سے قبل کی نازل شدہ قرار دیں اور وہ وجہ یہ تھی کہ عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل ماضی سے پہلے اِذَا آجائے تو اس کے معنے عام طور پر مستقبل کے ہوجاتے ہیں اور چونکہ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ کی آیت میں اِذَا فعل ماضی پر آیا ہے.اس لئے اس آیت میں مفسرین نے مستقبل کے معنے کرتے ہوئے آیت کا یہ مفہوم قرار دیا کہ اسلام کو آئندہ زمانہ میں فتح اور نصرت حاصل ہو گی او ریہ کہ اسلام میںکثرت سے لوگ داخل ہوں گے.اور چونکہ یہ ضروری ہے کہ پیشگوئی اس واقعہ سے پہلے ہو جس پر اس کو چسپاں کیا جاتا ہے وگرنہ وہ پیشگوئی نہیں رہتی.اس لئے ایک طرف تو ہمارے مفسرین نے اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ کی آیت کو پیشگوئی قراردیا.اور دوسرے طرف انہوں نے اس آیت میں اَلْفَتْحُ سے مراد فتح مکہ اور رَاَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ اَفْوَاجًا سے فتح مکہ کے بعد کثرت سے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ مرادلے لئے.اب اگر مفسرین اس سورۃ کا نزول حجۃ الوداع میں مانتے تو یہ آیت پیشگوئی کی حامل قرار نہ پاتی.کیونکہ اس کا مصداق پہلے آچکا تھا یعنی حجۃ الوداع ۱۰ ھ میں ہواہے اور فتح مکہ ۸ہجری میں.پس مفسرین کی بات تبھی بن سکتی تھی
Page 320
جب وہ یہ فیصلہ کرتے کہ سورۃ نصر فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی تھی.کیونکہ ان کے نزدیک اس آیت کا مصداق فتح مکہ کا واقعہ تھا(فتح البیان تفسیر سورۃ النصر).پس وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ یہ قرار دیں کہ سورۃ نصر کا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا تھا.وگرنہ اس کے بغیر ان کی تفسیر درست قرار نہ پاسکتی.حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ میں اَلْفَتْحُ سے مراد فتح مکہ ہی لی جاتی.کیونکہ فتح مکہ کی خبر قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں بڑی وضاحت سے آچکی ہے.اس لئے اس فتح کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کسی خاص سورۃ کے نازل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مثلاًاللہ تعالیٰ نے پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ( القصص:۸۶) یعنی اے محمد رسول اللہ تیرا خدا تجھے پھر مکہ میں واپس لائے گا.اور یہ ظاہر ہے کہ وہ مکہ جس پر آپؐکے دشمنوں کا قبضہ تھا.اس میں آپ اسی صورت واپس آسکتے تھے جبکہ وہ فتح ہو.اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا سکھلائی گئی کہ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ( بنی اسـرآءیل:۸۱) اب گو یہ ایک دعا ہے مگر الہامی دعا ہے.اور الہامی دعا وہی ہو سکتی ہے جو واقعات کے مطابق ہو.بہر حال اس میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ الٰہی ! میرا مکہ سے نکلنا بھی میری کامیابی کا موجب ہو اور ایسا نشان ہو جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہو اور میرا مکہ میں واپس آنا بھی میری کامیابی کا موجب ہو اور ایسا نشان ہو جو ہمیشہ قائم رہے.پس فتح مکہ کی خبر چونکہ سورۃ نصر کے نزول سے بہت عرصہ پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا چکی تھی اس لئے ہمارے لئے کوئی مجبوری نہیں کہ ہم سورۃ نصر کو فتح مکہ پر چسپاں کریں.اور اس لحاظ سے بھی ہم فتح مکہ پر اس کو چسپاں نہیں کرسکتے کہ روایات سے ثابت ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب نازل ہوئی تھی.پس درحقیقت اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے زمانہ کے متعلق پیشگوئی کی گئی ہے.یہ بتانے کے لئے کہ یہ فتوحات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی ہیں ان کا سلسلہ صرف آپؐکی حیات تک محدود نہیں بلکہ آئندہ بھی ان کا سلسلہ جاری رہے گا.چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قیصرِ روما سے جنگ چھڑی اور پھر حضرت عمررضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کسریٰ اور قیصر کو مکمل طور پر شکست ہوگئی.پس اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ میں ان فتوحات کا ذکر تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓکے زمانہ میں ہونے والی تھیں.اور یہی فتوحات آپؐکی تسلّی اور تشفی کا زیادہ موجب ہو سکتی تھیں کیونکہ انسان جب وفات کے قریب پہنچتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ میرا کام میری وفات کے بعد بھی جاری رہے گا یا نہیں.پس سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ
Page 321
گھبرائیںنہیں.کیونکہ اسلام کی فتوحات کا سلسلہ بند نہیں ہوگا بلکہ جاری رہے گا.اور اسلام دنیا پر غالب آجائےگا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ چونکہ آئندہ اسلام میں لوگ گروہ درگروہ داخل ہونے والے ہیں.اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نو مسلموں کے لئے دعا کرنی چاہیے.تاان کی صحیح تربیت ہو کر اسلام میں کسی خرابی کی بنیاد نہ پڑے اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کا سامان پیدا کردے.سورۃ نصر کے متعلق بعض مستشرقین یورپ کی آراء کی تردید پادری وہیری نے اپنی کتاب کمنٹری اون قرآن میں سورۃ نصر کے ماتحت بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ گویہ سورۃ مکہ میں بنائی گئی تھی ( جیسے کہ جنگِ حنین کے بعد نازل ہونے کی روایات بیان ہوئی ہیں ) لیکن اس کا سٹائل اور طرز بیان مدنی سورتوں کے ساتھ ملتا ہے.پھر نولڈ کے کی رائے بیان کرتا ہے کہ اس کی رائے یہ ہے کہ یہ سورۃ اس وقت بنائی گئی تھی جب محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ پر حملہ کرنے کے لئے بالکل تیار تھے اور ان کو اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا اور آپ کو فتح کے آثار نظر آرہے تھے.اس لئے یہ سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مذہب کی کامیابی کی امید کو ظاہر کرتی ہے.اس کے بعد وہیری لکھتا ہے کہ ان امور سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ سورۃ ۸ ھ کی ہے.مستشرقین یورپ اور دیگر پادری صاحبان چونکہ قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب قراردیتے ہیں اس لئے وہ عام طور پر سورتوں کے سٹائل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی.چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں سورۃ کا سٹائل اس قسم کا ہے جیسے مکی سورتوں کا ہوتا ہے اس لئے وہ مکی ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ فلاں سورۃ کا سٹائل ایسا ہے جیسے مدنی سورتوں کا ہوتا ہے اس لئے وہ مدنی ہے.حالانکہ وہ اتنی عربی بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی عبارت سے صحیح نتائج اخذ کرسکیں.پس عربی زبان سے اتنی کم واقفیت کے باوجود سورتوں کے سٹائل سے ان کے مکی اور مدنی ہونے کا استدلال کرنامحض ایک ڈھکونسلا ہوتا ہے.سورتوں کے سٹائل کو دیکھ کر مکی اور مدنی قراردینے کا ان کے پاس صرف ایک ہی معیار ہوتا ہے کہ جن سورتوں کی آیات چھوٹی ہوتی ہیں اوراُن میں وزن کا خیال رکھا گیا ہے وہ مکی ہیں اور جن سورتوں کی آیات لمبی ہیں اوران میں وزن کا خیال نہیں رکھا گیا وہ مدنی ہیںحالانکہ ان کے اس معیار کی تغلیط خود قرآن کریم سے ہی ہو جاتی ہے.چنانچہ سورۃ نوح مکی سورتوں میں سے ہے لیکن اس کی آخری آیت خاصی لمبی ہے.اسی طرح سورۃ دھر مدنی ہے لیکن اس میں وزن کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کی آیات بہت لمبی بھی نہیں ہیں.اسی طرح سورۃ انفال کے بعض ٹکڑے ایسے ہیںجن کے متعلق اگر سٹائل کو مدّ نظر رکھا جائے تو انہیں مکی قرار دینا پڑے گا.جیسے یہ آیت کہ لِّيَهْلِكَ مَن
Page 322
هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّ يَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ( الانفال: ۴۳) اگر سٹائل کو مدّ ِنظر رکھ کر سورتوں کے مکی او رمدنی ہونے کا فیصلہ کیا جائے تو یہ سورۃ مکی ہونی چاہیے.حالانکہ یہ آیت سورۃ انفال میں ہے جو قطعی طور پر مدنی ہے.بلکہ اس وقت کے قریب نازل ہوئی تھی جب مکہ فتح ہواتھا.پس سٹائل والی باتیں محض ڈھکونسلا ہیں نہ یہ کوئی قانون ہے اور نہ مستشرقین کو اتنی عربی آتی ہے کہ ان کی بات کو معقول قرار دیا جا سکے.وہیری کے خود ساختہ غلط معیار پر جب سورۃ نصر پوری نہیں اتری تو اس نے کہہ دیا کہ گویہ سورۃ مکہ میں بنائی گئی تھی لیکن اپنے سٹائل کے لحاظ سے یہ مدنی سورتوں سے ملتی ہے.حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم خدائے علیم و خبیر کی نازل کردہ کتا ب ہے اور یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے اور کسی خاص جگہ و مقام کی وجہ سے اس کے طرزِ بیان پر کوئی فرق نہیں پڑتا.پس سٹائل سے کسی سورۃ کے مکی اور مدنی ہونے کا اندازہ لگانا ایک غلط طریق ہے جس کو مستشرقین نے اختیا رکیا ہے.وہیری نے نولڈ کے کی اس رائے کو بھی لکھا ہے کہ یہ سورۃ اس وقت بنائی گئی تھی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کے لئے تیارتھے اور آپؐکو اپنی کامیابی کا پورا یقین تھا.گویا یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھ کر کہہ دیا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے.نولڈکے کی یہ رائے بھی محض تعصب کی بنا پر ہے.بھلا اگرمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ آئندہ حالات کو قیاس کر کے بنائی تھی تو آپؐنے ابتدائی مکی زندگی میں یہ قیاس کس طرح کر لیا کہ میری مخالفت اس قدر شدت اختیار کر جائے گی کہ ایک وقت وہ بھی آجائے گا جب آپؐمکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو ں گے اور ہجرت کے کچھ عرصہ بعد فاتحانہ شان میں مکہ میں داخل ہوں گے اور پھر مکہ کو آپؐمرکز نہیں بنائیں گے بلکہ مدینہ میں ہی قیام فرمائیں گے.ایک انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ آئندہ آنے والے دن میں کیا وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں.لیکن اتنی تحدّی سے ایسے حالات کا بیان کرنا جو واہمہ میں بھی نہیں آسکتے کسی قیاس کی بنا پر نہیں ہو سکتا.چنانچہ سورۃ البلد جو مکی سورۃ ہے اور مستشرقین اس کو ابتدائی مکی قرار دیتے ہیں.اس میں لَاۤ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَ اَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ( البلد:۲،۳) کے الفاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کرنے اور پھر مکہ کو فتح کر کے اس میں عارضی قیام کی خبر دی گئی ہے.اسی طرح سورۃ قصص مکی سورۃ ہے اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی پیشگوئی ہے اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ( القصص:۸۶) اے محمد رسول اللہ وہ خدا جس نے تجھ پر قرآن نازل کیا ہے وہ تمہیں فاتحانہ شان سے واپس مکہ لائے گا.پس یہ ساری باتیں غیب کی ہیں جو انسانی قیاس میں نہیں آسکتیں اور نہ انسانی دماغ ان کو سوچ سکتا ہے.پس ان غیب کی باتوںکو سامنے رکھ کر اس بات کومانے بغیر چارہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خدائے علیم و خبیر سے تھااور
Page 323
اس خدا نے ہی آپؐکو یہ باتیں بتائی تھیں.اور اس قسم کی باتیں دوتین نہیں بلکہ بیسیوں ہیں.جن سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے اور ایک غیر متعصب انسان جب ان باتوں پر ادنیٰ سابھی غور کرتا ہے تو اس کے منہ سے بے ساختہ یہ نکل پڑتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول تھے.پھر جنگِ احزاب کو ہی لے لو.اس میں سب قبائلِ عرب مدینہ میں حملہ کرنے کے لئے اکٹھے ہوگئے.مسلمان ان کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتے تھے.لیکن مسلمانوں کی حفاظت ہوئی اور ان کے مخالفین خود ہی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کا بال تک بیکا نہ ہوا.ان سب حالات کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دی گئی.جب کہ یہ قیاس بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپؐہجرت کریں گے اور پھر ہجرت کے بعد مقابلے ہوں گے اور عرب اپنی ساری طاقت سے مسلمانوں کو تباہ کر نے کے لئے جمع ہو جائیں گے.مگر وہ پسپا ہوں گے چنانچہ ان سارے حالات کو سورۃ قمر میں جو مکی سورۃہے سَیُھْزَمُ الْجَمْعُ وَیُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے.اس جنگ میں اپنے بچائو کے لئے مسلمان خندق کھودرہے تھے اور ایک جگہ پتھر آگیا اور وہ ٹوٹتا نہیںتھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی.آپؐخود توڑنے کے لئے تشریف لائے اور آپؐنے کدال مارا اور پتھر سے آگ نکلی تو آپؐنے زور سے اللہ اکبر کہا.پھر دوسرا کدال مارا تو پھر آگ نکلی اور آپؐنے اللہ اکبر کہا.پھر تیسرا کدال مارا اورآگ نکلی تو آپؐنے اللہ اکبر کہا اور پتھر ٹوٹ گیا.لوگوںنے سوال کیایا رسول اللہ آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ فرمایا پہلی دفعہ مجھے کسریٰ کے محلات دکھائے گئے اور مجھے جبریل نے بتایا کہ میری امت ان پر قابض ہوگی.اور دوسری مرتبہ روم اور شام کے سرخ محلات کا مجھے نظارہ کر ایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بھی میری امت کے قبضہ میں آئیں گے.پھر تیسری مرتبہ صنعاء کے محلات مجھے دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ بھی مسلمانوں کو ملیں گے.( کامل ابن اثیر الاحداث فی السنۃ الـخامسۃ و البدایۃ والنـھایۃ غزوۃ خندق) الغرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں فتوحات کی خبریں دیں جبکہ یہ باتیں قیاس میں بھی نہیں آسکتی تھیں.پھر اس کے بعد ایسے حالات بھی پیش آئے جن میں بظاہر فتح کا سوال نہ تھا.بلکہ قیاس سے کام لینے والے منافق یہ کہتے تھے مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا(الاحزاب:۱۳) کہ محمد رسول اللہ کے سب وعدے محض فریب ہی تھے.اسی طرح منافق کہتے تھے.يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا.(الاحزاب:۱۴) کہ اے مدینہ والو! اب تمہارے لئے زمین تنگ ہو گئی ہے تم اپنے آپ کو ختم سمجھو.تم عرب قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
Page 324
اس لئے اپنے دین کی طرف لوٹ آئو.لیکن مخالف حالات کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سچی ہوئیں اور قیاس کرنے والوں کے قیاسات غلط ثابت ہوئے.عرب قبائل میدان چھوڑ کر بھاگ گئے.مسلمانوں کو کوئی آنچ نہ آئی اور اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ مکہ فتح ہوا.اسلام نے ترقی کی اور کسریٰ اور قیصر کے محلات مسلمانوں کے قبضہ میں آئے.وہیری اور اس کے ہم خیال یہ بتائیں کہ کیا یہ قیاسات ہیں؟ پھر ان باتوں کو بھی جانے دیجئے.ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ یہ باتیں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنالیں.لیکن ان خبروں کے متعلق کیا کہو گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانہ کے متعلق بیان فرمائیں.مثلاً فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جبکہ مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں گے اور اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور عیسائی کثرت سے پھیل جائیں گے اور آخر اللہ تعالیٰ اسلام کو دوبارہ ترقی دینے کے لئے مہدی اور مسیح کو مبعوث کرے گا(مشکٰوۃ کتاب العلم و شعب الایمان للبیھقی ).پس وہیری اورا س کے متبعین بتائیں کہ یہ خبریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قیاس سے معلوم ہو گئیں.حقیقت یہ ہے کہ جو امور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ سب خدائے علّام الغیوب سے معلوم کر کے بتائے وہ آپ کا قیاس نہیں تھا.پس سورۃ نصر کے متعلق یہ کہنا کہ یہ حالات کو دیکھ کر بنائی گئی تھی محض تعصّب یا غلط فہمی ہے.وہیری نے سورہ نصر کا زمانۂ نزول ۸ھ مقرر کیا ہے.یہ زمانۂ نزول ہماری تحقیقات کے لحاظ سے گو غلط ہے.جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیا ہے.لیکن اگر یہی زمانۂ نزول مانا جائے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ پورا ہوا اور جو بات سورۃ نصر میں بیان ہوئی تھی کہ گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہوں گے وہ ۹،۱۰ھ میں پوری ہو گئی.اور یہ بات واضح ہوگئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول ہیں.یہ امر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری بیان کردہ ترتیب کے مطابق یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ خاص طور پر تعلق رکھتی ہے کیونکہ ہماری تحقیقات میں تیسویں پارے کے آخر میں سورتوں کی ترتیب اس طور پر ہے کہ ایک سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والی سورۃ میں آپؐکی بعثتِ ثانیہ کا.چنانچہ یہ ترتیب سورۃ البیّنہ سے شروع ہوتی ہے.سورۃ البیّنہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ اولیٰ کا ذکر تھا اور سورۃ الزلزال میں آپؐکی بعثتِ ثانیہ کا ذکر کیا گیا ہے.اور اس طرح آگے ترتیب چلتی چلی گئی ہے.لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ جس سورۃ میں اسلام کے ابتدائی زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں آخری زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ یہ کہ جس سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا.بالعموم
Page 325
دونوں ہی ذکر ہوتے ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک سورۃ میں مدّ ِنظر اسلام کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہےاور دوسری سورۃ میں خصوصیت کے ساتھ مدّ ِنظر اسلام کا آخری زمانہ ہوتا ہے.چنانچہ اسی ترتیب کے پیش نظر یہ بتایا جا چکا ہے کہ سورۃ نصر سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ کافرون میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتِ ثانیہ کا ذکر ہے.یعنی اس کا مضمون اس موجودہ زمانہ پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے.ہماری اس ترتیب کے مطابق سورۃ نصر کا مضمون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پر زیادہ چسپاں ہونا چاہیے.گویا یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لئے مقصود اوّل ہے.سورۃ نصر کا پہلی سورۃ سے تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ سورۃ کافرون میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐکے ساتھیوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اعلان کردیں کہ وہ اسلام کے منکروں کے معبودوں کی عبادت نہیں کرسکتے اور نہ ان عبادت کے طریقوں کو اختیار کرسکتے ہیں جن کو اسلام کے منکرین اختیار کئے ہوئے ہیں.اسی طرح کفار کے متعلق یہ بیان تھا کہ وہ اپنے عبادت کے طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں.اس کے بعد سورۃ نصر کو رکھ کر اس لطیف مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ تھوڑے عرصہ میں اسلام کو عظیم الشان فتوحات حاصل ہونے والی ہیں.اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع عملی طور پر یہ دیکھ لیں گے کہ جو طریق انہوں نے اختیار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی ہے تو کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریق کو اختیار کر یں جس کے ساتھ خد انہیں اور پھر جو شکست خوردہ طریق بھی ہے.اسی طرح جب کفار دیکھ لیں گے کہ ان کی جماعت ٹوٹ گئی اور تما م کار آمد لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے تو وہ بھی خواہ فطرتاً شرک کے حق میں ہوں مگر ان کی ضمیر ان کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کردے گی.پس گو وہ ظاہر میں مسلمانوں کا طریق عبادت اختیار کریں گے مگر درحقیقت یہ خدائی معجزہ کے ماتحت ہو گا.ان کی اپنی مرضی سے نہیں.اگر اپنی مرضی پر انہیں رہنے دیا جاتا تو اپنے آبائو اجداد کی تعلیم کے مطابق کبھی وہ اسلامی عبادت اختیار نہ کرتے.اسی طرح سورۃ نصر کا سورۃ کافرون کی آخری آیت کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے اور وہ یہ کہ سورۃ کافرون کی آخری آیت میں یہ کہا گیا تھا لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ کہ اے کافرو! تمہارے نزدیک غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے مذہب سے ذرا اِدھر اُدھر ہوا تم لٹھ لے کر کھڑے ہو گئے.اس کو مارا پیٹا اور اس کی جان لینے کے درپے ہوگئے اور اس کو جبرو اکراہ سے اپنے بتوں اور معبودوں کی طرف لانے کی کوشش کی اور ہر طرح کا ظلم روا سمجھا.لیکن اسلام ایسے غلبہ کو غلبہ نہیں بلکہ شکست سمجھتا ہے اور اسلام کے نزدیک غلبہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے دلائل پیش کئے جائیں جودل و دماغ پر قابو پالیں اور ایک ہوش مند انسان ان دلائل کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور ہمیشہ کے لئے غلام
Page 326
ہوجائے اوریہ کہ مذہب کے بارہ میں جبر سے کام لینے کی بجائے دلائل و براہین سے کام لینا چاہیے.اور مذہب کے اختیار کرنے میں پوری آزادی ہونی چاہیے.اے کافرو! تم نے اپنے ہتھیار کو استعمال کیا اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیار کو استعمال کیا.اب تھوڑے دنوں میں نتیجہ نکل آئے گا کہ باوجود تمہارے پورے جبر کے تمہاری ساری قوم ٹوٹ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آگرے گی.اور یہ ظاہر ہے کہ جب تمہاری قوم مسلمان ہوجائے گی تو مسلمانوں کو تمہارے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی.پس جو دعویٰ سورۃ کافرون کی آخری آیت میں کیا گیا تھا وہ ثابت ہو جائے گا کہ غلبہ کے متعلق کفار کا نظریہ اور ہے اور مسلمانوں کا اور ہے.لیکن سچا نظریہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے کہ وہی جیتے گا جو دلیل سے کام لے گا اور تلوار اور سونٹا ناکام رہیں گے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا ( اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( شروع کرتا ہوں ) اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُۙ۰۰۲ جب اللہ کی مدد اور کامل غلبہ آجائے گا.حلّ لُغات.نَصْـرٌ.نَصْـرٌ.نَصَـرَ الْمَظْلُوْمَ نَصْـرًا کے معنے ہوتے ہیں اَعَانَہٗ یعنی مظلوم کی مدد کی.اور جب نَصَـرَ فُلَانًا عَلٰی عَــدُوِّہٖ وَمِنْ عَــدُوِّہٖ کہیں تو معنے ہوں گے نَـجَّاہُ مِنْہُ وَخَـلَّصَـہٗ وَاَعَانَہٗ وَقَوَّاہُ عَلَیْہِ کہ فلاں نے فلاں کی مدد کر کے اس کو اس کے دشمن سے نجات دلادی اور دشمن پر غالب کر دیا.(اقرب) اَلفَتْحُ.اَلفَتْحُ :.فَتَحَ الْـحَاکِمُ بَیْنَ النَّاسِ کے معنے ہوتے ہیں قَضٰی.حاکم نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کردیا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم.اور جب فَتَحَ الْسُّلْطَانُ دَارَالْـحَرْبِ کا فقرہ بولیں گے تو مراد یہ ہوگی کہ غَلَبَ عَلَیْھَا وَتَـمَلَّکَھَا یعنی بادشاہ اس علاقہ پر غالب آگیا جس سے جنگ چھڑی ہوئی تھی.نیز فَتَحَ کے معنے ہوتے ہیں.اس نے کوشش کی.وَاَقْبَلَتْ عَلَیْہِ الدُّنْیَا اور دنیا اس کے قدموں میں آگری.اور جب فَتَحَ اللّٰہُ عَلٰی نَبِیِّہٖ فَتْحًا کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ نَصَـرَہٗ.اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مددکی اور اس کو اس کے مخالفوں پر غالب کردیا.(اقرب) مفردات امام راغب میں لکھا ہے.اَلْفَتْحُ اِزَالَۃُ الْاِغْلَاقِ وَالْاِشْکَالِ.رکاوٹ اور بند کو دور کر دینا فتح
Page 327
کہلاتا ہے یعنی جب کسی چیز کے آنے کا راستہ بند ہو اور پھر اس کا راستہ کھول دیا جائے تو اس وقت فتح کا لفظ بولتے ہیں.( مفردات ) پس اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ کے معنے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت واعانت آجائی گی اور اللہ تعالیٰ اس بند کو توڑ دے گا جس کی وجہ سے کفار اسلامی طریقِ عبادت کو قبول نہیں کرتے تھے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو جائیں گے.کیونکہ کفار کی فطرتیں بدل دی جائیں گی اور ان کی ضمیر پر اسلام کو غلبہ دےدیا جائے گا.تفسیر.قبل ازیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ سورۃ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف ستّر دن پہلے نازل ہوئی تھی اور یہ کہ اس سورۃ کے نازل ہونے کے ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم بھی دے دیا گیا تھا کہ اب آپؐکی وفات کا وقت قریب ہے.یہ طبعی بات ہے کہ جب کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ عنقریب اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور اقرباء کو چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والا ہے تو وہ اس لحاظ سے متفکر ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اولاد، اس کے عزیز وں، رشتہ داروں اور متعلقین کا کیا بنے گا.سورۃ فتح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کی حفاظت اور ترقی کی پیشگوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشا تھا.اس لحاظ سے آپؐکو اپنے جسمانی عزیزوں اور اقرباء کے متعلق تو کوئی فکر دامنگیر نہیں ہو سکتا تھا.ہاں اگر خیال آسکتا تھا تو یہی کہ کہیں آپؐکے بعد آپؐکی اُمّت میں کوئی خلل تو پیدا نہ ہوگا اور اگر پیدا ہوا تو اس کے متعلق کیا صورت ہو گی اور نبی کی وفات پر عام طور پر اس کے متبعین گھبرا جاتے ہیں اور نبی کی وفات کو بے وقت موت سمجھا جاتا ہے اور مخالفین بھی اس خیال میں ہوتے ہیں کہ اس نبی نے تو اپنے زمانہ میں کام چلا لیا ہے.لیکن اس کی وفات کے بعد اس کا لگایا ہوا پوداختم ہو جائے گا.اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر میں ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ متفکر نہ ہوں.یہ فتوحات جو آپ کے زمانہ میں ہوئی ہیں یہ رُک نہیں جائیں گی.بلکہ ان کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا اور اسلام میں اگر آپ کے زمانہ میں بیک وقت سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے ہیں تو آپ کے بعد ہزاروں کی تعداد میں شامل ہوں گے اور حضور کے چشمہ سے فوج در فوج لوگ سیراب ہوں گے اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے وجودوں کو کھڑا کر دے گا جو آپ کی اُمّت کو سنبھال لیں گے اور اس میں کسی قسم کا رخنہ پیدا نہ ہونے دیں گے.اور مخالفین جو سمجھتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپؐکا سلسلہ ختم ہو جائے گا ان کی خوشیاں پامال ہو جائیں گی.
Page 328
اوراسلام دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گا اور جو مشکلات پیش آئیں گی وہ خش وخاشاک کی طرح اڑ جائیں گی.گویا اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر کو نازل کر کے ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلّی دی اور دوسری طرف آپؐکے متبعین کو یہ ہدایت کی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر گھبرا نہ جائیں.جس خدا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران کیا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے اور وہ آپؐکی وفات کے بعد آپؐکی اُمّت کا محافظ ہوگا اور آپؐکے بعد صحابہ کو یتیم کی صورت میں دیکھ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ مدد کرے گا اور اس کی نصرت کے دروازے بند نہیں ہوں گے بلکہ اور بھی زیادہ کھل جائیں گے اور اس نصرت کو دیکھ کر لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے شروع ہو جائیں گے.اور آسمانی بادشاہت کا قیام ہو جائے گا او رساری دنیا توحید کے نُور سے منور ہوجائے گی.مزید برآں مخالفین کی جھوٹی خوشیاں بھی پامال ہو جائیں گی.چنانچہ یہ وعدہ جس رنگ میں پورا ہوا اس کو ہرغیر متعصب آدمی دیکھ کر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول تھے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور مخلص لوگوں کے بھی قدم لڑکھڑا گئے اور ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بظاہر بے وقت سمجھا جانے لگا اور پھر خلافت کے انتخاب پر بھی فتنہ کے آثار نظر آرہے تھے.کیونکہ انصار یہ چاہتے تھے کہ خلیفہ ان میں سے منتخب کیا جائے اور مہاجرین کی یہ رائے تھی کہ عرب لوگ سوائے قریش کے کسی اور سے دبنے کے نہیں.اس فتنہ کو دیکھ کر مخالفین یہود اور دوسرے لوگ اس خیال سے خوش تھے کہ اسلام اب ختم ہے.لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً گرتی ہوئی قوم کو سنبھال لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کردیا اور انہوں نے قوم کی باگ ڈور سنبھال لی اور جو لوگ انصار میں سے تھے اور چاہتے تھے کہ ان میں سے خلیفہ کا انتخاب ہو ان کو بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف مائل کردیا.پھر ابھی قوم کا شیرازہ سنبھلنے نہ پایا تھا کہ عرب کے بعض قبائل نے ارتداد کا اعلان کر دیا اور ان کے سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں.اسی طرح سے متعدد جھوٹے مدعیانِ نبوت اٹھ کھڑے ہوئے.مزید برآں بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا.ان مشکلات کے ساتھ موتہ کی مہم علیحدہ درپیش تھی جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں رومیوں سے حضرت زیدؓ بن حارثہ کے خون کا انتقام لینے کے لئے ان کے لڑکے اسامہؓ بن زید کی ماتحتی میں شام بھیجنے کا حکم دیا تھا ابھی یہ مہم روانہ نہ ہوئی تھی کہ آپؐکا انتقال ہو گیا.یہ سب حالات اس قسم کے تھے
Page 329
کہ ایسے حالات میں ایک اچھا دلیر اور مضبوط دل والا انسان بھی گھبرا جاتا ہے.لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے ایسی سکینت اور اطمینان نازل کیا کہ آپ گھبرائے نہیں اور آپ اسی وثوق اور یقین پر تھے کہ خدا کے وعدے بہر حال پورے ہوں گے.زمین و آسمان بے شک ٹل جائیں لیکن خدا کی باتیں نہیں ٹل سکتیں.اور اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ کی آیت ان کی ڈھارس کو باندھے ہوئے تھی.چنانچہ صحابہ کرام نے ان مخدوش حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضرت اسامہ ؓ بن زید کو موتہ کی مہم کے لئے نہ بھجوایا جائے اور سب سے پہلے ان فتنوں کا تدارک کیا جائے جو اندرون عرب پیدا ہو گئے ہیں.یعنی مرتدین اور زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ اور جھوٹے مدعیان کا فتنہ.مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سختی سے صحابہؓ کی بات کا انکار کر دیا اور فرمایاکہ جس لشکر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس کو روکنے کا حق ابو بکر کو کہاں ہو سکتا ہے.وہ لشکر بہر حال اپنی مہم پر روانہ ہو گا.خواہ مدینہ کی یہ حالت ہو جائے کہ اس پر دشمن ٹوٹ پڑیں اور ہماری لاشوں کو درندے گھسیٹ رہے ہوں(البدایۃ والنـھایۃ فصل فی تنفیذ جیش اسامۃ بن زید) یہ فقرات اس شخص کی زبان سے ہی نکل سکتے ہیں جو اس یقین سے پُر ہو کہ اسلام کا غالب آنا خدا کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے اور یہ تقدیر ٹل نہیں سکتی خواہ ساری دنیا ہی اس کے مقابلہ کے لئے آکھڑی ہو.غور کریں کہ یہ یقین اور یہ ثبات اور یہ دلیری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہاں سے حاصل ہو گئی.یہ محض اس خدا نے آسمان سے نازل کی تھی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت تسلی دی تھی کہ آپ گھبرائیں نہیں آپ کے بعد ہر لمحہ خدا کے فرشتے نصرت اور فتح کو لے کر اتریں گے.یہاں تک کہ اسلام کا علَم ساری دنیا پر لہرا جائے گا.چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی خلافِ مرضی حضرت اسامہؓ بن زید کو لشکر سمیت موتہ کی طرف روانہ کر دیا.چنانچہ چالیس دن کے بعد یہ مہم اپنا کام پورا کر کے فاتحانہ شان سے مدینہ واپس آئی.اور خدا کی نصرت اور فتح کو نازل ہوتے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا.پھر اس مہم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جھوٹے مدعیان کے فتنے کی طرف متوجہ ہوئے اور اس فتنہ کی ایسی سرکوبی کی کہ اس کو کچل کر رکھ دیا اور یہ فتنہ بالکل ملیا میٹ ہو گیا.بعد ازاں یہی حال مرتدین کا ہوا.جو لوگ زکوٰۃ کے منکر تھے ان کی تعداد کافی تھی اور صحابہ کبار بھی ان سے لڑنے کے بارے میں حضر ت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے تھے.اور کہتے تھے کہ جولوگ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیںاور صرف زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں ان پر کس طرح سے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے.اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہایت جرأت اور دلیری سے کام
Page 330
لیتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اونٹ کی ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا اگر وہ اس کے دینے سے انکار کر ے گا تو آپ اس کا مقابلہ کریں گے.آپ کے اصرار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی آپ کی اصابتِ رائے کا اعتراف کرنا پڑا اور وہ سمجھ گئے کہ اگر آج زکوٰۃ نہ دینے کی اجازت دے دی گئی تو آہستہ آہستہ لوگ نماز روزہ کو بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور اسلام محض نام کا رہ جائے گا.الغرض ایسے حالات میں حضرت ابو بکرؓنے منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا اور انجام یہی تھا کہ اس میدان میں بھی آپ کو فتح اور نصرت حاصل ہوئی.اور تمام بگڑے ہوئے لوگ راہِ حق کی طرف لوٹ آئے.حقیقت یہی ہے کہ اگر اسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے اور برگزیدہ رسول نہ ہوتے.تو یہ حالات مسلمانوں کو مٹانے کے لئے کافی تھے لیکن کیا بات تھی کہ مسلمان آگ کے شعلوں اور موت کے منہ سے بھی نکل آئے اور ان کا بال تک بیکا نہ ہوااورہر گھڑی فتح و نصرت ان کے ساتھ رہی.وہ یہی وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا.کہ اے رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی قوم کی دستگیری اللہ تعالیٰ کرے گا اور اسے ہر میدان میں فتح مند کرے گا.پھر ابھی اندرونی خلفشار ختم ہی ہوئی تھی کہ عراق میں ایرانی حکومت کے ساتھ جنگ شروع ہوگئی.ایرانی حکومت ان دنوں بڑی ترقی یافتہ حکومت تھی او راس کی فوج تربیت یافتہ اور ان کے پاس بہت سازو سامان تھا اور مسلمان ان کے مقابلے میںایسے ہی تھے جیسے باز کے مقابلہ میں چڑیا کی حیثیت ہوتی ہے.لیکن جوں ہی عراق میں معرکے شروع ہوئے یکے بعد دیگرے ایرانیوں کو خطرناک طور پر شکست ہوئی اور ان کو پسپا ہونا پڑا.ابھی مسلمان اس طرف سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ شام اور مصر میں رومیوں سے جنگ چھڑ گئی اور دمشق، اردن، حمص اور فلسطین میں سب طرف فوجوں کو بھیجنا پڑا اور سب طرف جنگ کے شعلے بلند ہو نے شروع ہو گئے.ایسے نازک حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور آپ کی وفات ہو گئی.اللہ تعالیٰ کی نصرت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مسندِ خلافت پر بٹھا دیا.آپ کے عرصہ خلافت میں سب طرف جنگ کا میدان گرم رہا اور ان جنگوں میں بعض اوقات مسلمانوں میں سے ایک ایک آدمی نے اپنے مخالفوں میں سے ایک ایک ہزار کا مقابلہ کیا اور مخالفوں کی لاکھوں کی تعداد میں آنے والی فوج کو چند ہزار مسلمانوں نے روند ڈالا اور وہ ہرمیدان سے کامیاب و کامران آئے.اور ایران اور روم جیسی عظیم الشان ترقی یافتہ سلطنتوں کے پرخچے اڑا دئیے.اور مصر، شام، فلسطین اور ہندوستان کی سرحد سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا.حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانۂ خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانۂ خلافت شروع ہوااور
Page 331
اس میں بھی مسلمان سیلاب کی طرح بڑھتے چلے گئے اور خراسان، افغانستان اور سندھ تک قبضہ کر لیا.اور شمالی افریقہ کے علاقے طرابلس، تونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ فتح کر لئے اور یورپ کی سرحد تک مسلمان پہنچ گئے اور مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے سب علاقہ کو روند ڈالا.یہ سب فتوحات اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ کے وعدے کے مطابق تھیں.اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے فرستادہ اور رسول نہ ہوتے تو مزید کامیابی تو کجا مسلمانوں کا اپنا شیرازہ بھی آپ کے بعد بکھر جاتا.لیکن نہ صرف یہ کہ مسلمان ایک نقطہ پر جمع رہے بلکہ ہر طرف فتح نے ان کی پیشانیوں کو چوما.یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے مطابق تھا جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے وقت کئے تھے.اس آیت کے متعلق یہ امر بھی ذکر کے قابل ہے کہ اس میں اَلْفَتْح پر ال داخل کیا گیا ہے اور عربی زبان میں جب کسی لفظ پر ال داخل کیا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ مخاطب اس امر کو جانتا ہے.جیسے رَجُلٌ کے معنے ہوں گے کوئی آدمی.اور جب اس پر ال داخل کردیں اور کہیں الرَّجُلُ تو اس کے معنے ہوں گے وہ خاص آدمی جس کو متکلم اور مخاطب دونوں جانتے ہیں.پس آیت اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ میں اَلْفَتْحُ پر ال داخل کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ فتح جس کے وعدے دئیے جارہے ہیں ایسی ہے کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور یہ بات درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نظارے کشف میںدکھا دئیے تھے.اور بتا دیا تھاکہ وہ دن دور نہیں جب کہ ایران اور روم کے ملک مسلمانوں کے قبضہ میں آجائیں گے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لارہے تھے تو راستے میں ایک شخص سراقہ نے آپ کا تعاقب کیا.اس کی نیت خراب تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی.باربار سراقہ کا گھوڑا ریت میں دھنس جاتاتھا.اس وقت آپؐنے سراقہ کو بلایا اور کہا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ شاہِ ایران کے کنگن دیکھتا ہوں.سراقہ ابھی مسلمان نہیں تھا.بعد ازاں ان کو قبول اسلام کی توفیق ملی اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب کسریٰ شاہِ ایران کے کنگن آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکماً ان کنگنوں کو سراقہ کے ہاتھوں میں پہنایا.پھراسی طرح جنگِ احزاب میں جب مسلمان اپنی حفاظت کے لئے خندق کھود رہے تھے تو ایک ایسا پتھر آگیا جو ٹوٹتا نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور آپ اپنا کدال لے کر تشریف لائے.اور تین بار کدال مارا.اور ہربار اللہ اکبر بلند آواز سے فرمایا اور پتھر ٹوٹ گیا.تب آپ نے اپنے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ کیوں آپ نے اللہ اکبر کہا.تب صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیں.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں
Page 332
نے پہلی بار کدال مارا تو مجھے کسریٰ کے محلات دکھائے گئے اورمجھے بتایا گیا کہ میری امت اس پر قابض ہو گی.تب میں نے اللہ اکبر کہا اور پھر دوسری بار کدال مارا تو روم اور شام کے سُرخ محلات کا نظارہ مجھے کرایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بھی میری امت کو ملیںگے.اس پر میں نے پھر اللہ اکبر کہا.پھر تیسری بار جب میںنے کدال مارا تو مجھے صنعاء کے محلات دکھائے گئے اور بتایا گیا کہ اس پر بھی میری امت قابض ہو گی.الغرض یہ فتوحات جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں ہوئیں سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشفاً دیکھ چکے تھے اور ان کو جانتے تھے.چنانچہ اس آیت میں اسی وجہ سے اَلْفَتْحُ پر ال داخل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت آجائے گی اور موعودہ فتوحات حاصل ہو جائیں گی جن کا نظارہ آپ کو کشفاً دکھایا گیا ہے تو اس وقت لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوں گے نیز اَلْفَتحُ میں اَ ل کمال کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے اور معنے یہ ہوں گے کہ جب کامل فتح آجائے گی.وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًاۙ۰۰۳ اور تُو ( اس بات کے آثار ) دیکھ لے گا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے.حلّ لُغات.رَاٰی.رَاَیْتَ رَاٰی سے فعل ماضی کا صیغہ ہے اور رَاٰی یَرَی رُؤْیَۃً کے معنے ہوتے ہیں نَظَرَ بِالْعَیْنِ اَوْ بِالْقَلْبِ کہ ظاہری آنکھ سے دیکھا یا دل کی آنکھ سے.(اقرب) پس رَاَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ کے معنے ہوں گے.تُو دل کی آنکھ سے دیکھ لے گا.اَفْوَاجًا.اَفْوَاجًا.اَفْوَاجٌ فَوْجٌ کی جمع ہے اور اَلْفَوْجُ کے معنے ہوتے ہیں.اَلْـجَمَاعَۃُ مِنَ النَّاسِ لوگوں کا ایک گروہ اور جماعت.اَوِ الْـجَمَاعَۃُ الْمَارَّۃُ السَّـرِیْعَۃُ.یا ایسی جماعت جو جلدی سے گذر جائے.اور رَاَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ اَفْوَاجًا کے معنے ہوں گے اَیْ طَائِفَۃٌ بَعْدَ اُخْریٰ کہ تُو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے.(اقرب) تفسیر.وَ رَاَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ اَفْوَاجًا.یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور موعود فتح آجائے گی اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے دیکھ لے گا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو آپ نے فوج در فوج لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتے کس طرح دیکھا.اس
Page 333
کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ حل لغات میں لکھا جا چکا ہے.رُؤْیَت کا لفظ صرف آنکھ سے دیکھنے پر استعمال نہیں ہوتا.بلکہ یہ دل سے کسی چیز کو پا لینے یا اس کا علم حاصل کر لینے پر بھی بولا جاتا ہے.اور اسی طرح کشفاً کسی چیز کو دیکھنے پر بھی استعمال ہوسکتا ہے.نیز عربی محاورہ میں یقینی اور قطعی خبر کو بھی دیکھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے.چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے.اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ ( الفیل:۲ ) یعنی اے محمد رسول اللہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اصحاب الفیل کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا.حالانکہ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی ایک سال پہلے ہوا تھا تو گویا یہاں پختہ علم کے لئے رَاَیْتَ کا لفظ استعمال ہوا ہے.پس رَاَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰہِ اَفْوَاجًا کے معنے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی فتوحات آجانے کے بعد جس طرح لوگوں نے جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا ہے یہ نظارہ اللہ تعالیٰ تجھ کو کشفاً دکھا دے گا.یا اس کے آثار پیدا کر کے یہ یقین تیرے دل میںپیدا کر دے گا کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا.فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرْهُ١ؔؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًاؒ۰۰۴ پس اس وقت تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ ( ساتھ ) اس کی پاکیزگی ( بھی ) بیان کرنے میں مشغول ہو جائیو اور اس سے ( اپنی قومی تربیت کی کوتاہیوں پر ) پردہ ڈالنے کی دعا کیجئیو.وہ یقیناً اپنے بندے کی طرف رحمت کے ساتھ لوٹ لوٹ کر آنے والا ہے.حلّ لُغات.سَبِّحْ سَبِّحْ سَبَّحَ سے امر کا صیغہ ہے اور سَبَّحَ اللّٰہَ کے معنے ہیں نَزَّھَہٗ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام معائب اور برائیوں سے پاک قرار دیا (اقرب) فَسَبِّحْ کے معنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر قسم کے معائب اور نقائص سے پاک قرار دے دو.اِسْتَغْفِرْہُ.اِسْتَغْفِرْہُ.اِسْتَغْفَرَ غَفَرَ سے باب استفعال کا صیغہ ہے اور غَفَرَ الشَّیْءَ غَفْرًا کے معنے ہوتے ہیں سَتَرَہٗ.کسی چیز کو ڈھانپ دیا.اور جب غَفَرَ الْمَتَاعَ فِی الْوِعَاءِ کہیں تو معنے ہوں گے اَدْخَلَہٗ وَسَتَرَہٗ کہ سامان کو تھیلے یا ٹرنک میں رکھ کر محفوظ کر دیا اور غَفَرَ اللہُ لَہٗ ذَنْبَہٗ کے معنے ہوتے ہیں.غَطَّی عَلَیْہِ وَعَفَا عَنْہُ.اس کے قصور کو ڈھانپ دیا اور اس کی کمزوری پر پردہ ڈال دیا.تا کہ لوگوں کو نظر نہ آئے.(اقرب) مفردات میں ہے کہ اَلْغَفْرُ کے معنے ہیں اِلْبَاسُ مَا یَصُوْنُہٗ عَنِ الدَّنَسِ کہ جب کسی چیزکو مَیل اور گرد سے
Page 334
محفوظ رکھنے کے لئے اس پر کوئی چیز ڈال دیں تو اس وقت اس کے لئے غفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں.اِغْفِرْ ثَوْبَکَ فِی الْوِعَاءِ کہ اپنے کپڑے کو گرد اور مَیل سے بچانے کے لئے کسی تھیلے یا ٹرنک میں رکھ دو.(مفردات) پس اِسْتَغْفِرْہُ کے معنے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اپنی بشری کمزوری پر پردہ پوشی طلب کرو.یعنی دعا کرو کہ تمہارے ماننے والوں میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدانہ ہو اور وہ صحیح راستہ پر قائم رہیں.تفسیر.تسبیح کے ساتھ تحمید کرنے کا حکم دینے میں حکمت سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ.جیساکہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے.سَبَّحَ کے معنے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیوب اور نقائص سے مبرّا قرار دینے کے ہوتے ہیں اور حمد کے معنے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تمام خوبیوں کے ہونے کا اقرار کیا جائے.گویا اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اگرمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہماری نصرت ختم ہو جاتی اور فتوحات کا سلسلہ بند ہو جاتا تو مسلمان بجا طور پر کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کی اور اسی طرح کفار بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ مسلمانوں کو جو فتوحات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئیں وہ محض ان کی ذاتی قابلیت کے نتیجہ میں تھیں اور آپؐکی وفات کے بعد فتوحات کا رُک جانا اسلام کے سچا نہ ہونے کا بیّن ثبوت ہے.پس اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ان ہر دو امور سے بَری ثابت کرنے کے لئے اپنے رسولؐکو یہ اطلاع دے دی کہ نہ تو آپؐکی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑے گا اور نہ فتوحات کا سلسلہ بند ہو کر مخالفوں کے لئے خوشی کا موقع پیدا ہوگا.جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ نصر کی آیات کو نازل کر کے اپنے آپ کو ان الزاموں سے بَری ثابت کر دیا ہے تو اے رسول اللہ اب آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ پوری طرح اعلان کردیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے.نہ تو وہ اپنے بندوں کو بے یارومددگار چھوڑتا ہے کہ اس پر کوئی الزام عائد ہو اور نہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اور چونکہ اس نے باوجود مخالف حالات کے مسلمانوں کو غالب کردیا ہے اور آئندہ بھی غالب کرتا چلا جائے گا.اس لئے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی حمد کے گیت گائے جائیں اور یہ کہا جائے کہ ہر خوبی اس کی ذات میں پائی جاتی ہے.پھر اس آیت میں لفظ رَبّ استعمال فرمایا.یعنی یہ کہا ہے کہ اپنے رب کی حمد کرو.یہ نہیںکہا کہ اللہ کی حمد کرو.رَبّ کے معنوں کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ ادنیٰ حالت سے ترقی دیتے دیتے کمال تک پہنچانا.گویا رَبّ کا لفظ اس آیت میں استعمال کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تا یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس لئے حمد کا مستحق ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ضعف کی حالت سے اٹھا کر ساری دنیا کا مالک بنادیا.پس جو کسی پر اتنا فضل کرے وہ بہر حال حمد کا
Page 335
مستحق ہو گا.پھرحمد کے لفظ میں یہ اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ اے مسلمانو! فتوحات کو دیکھ کر تمہارے اندر کِبر پیدا نہ ہو.اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتوحات تمہاری کسی ذاتی قابلیتوں کی بنا پر ہیں.بلکہ یہ سب کچھ خدا کے فضل کے ماتحت تم کو مِل رہا ہے.اس لئے تمہیں خدا تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کے آستانے پر ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے.تا تمہارا یہ شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کو نازل کرنے کا موجب ہو.الغرض فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ کے الفاظ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانو تم اعلان کردو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق ہماری نصرت کر کے ایک طرف اپنی ذات کو تمام الزامات سے بَری ٹھہرالیا ہے اور دوسری طرف اپنی ذات کو حمد کا مستحق قرار دے لیا ہے.اِسْتَغْفِرْہُ:.اِسْتِغْفَار کا لفظ غَفْرٌ سے نکلا ہے.اور جیسا کہ حلِّ لغات میں بتایا جا چکا ہے غَفْرٌ کے معنے ڈھانکنے یا حفاظت کرنے کے ہیں اور استغفار کے معنے ہیں حفاظت کے لئے دعا یا طلبِ حفاظت.گویا استغفار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لے اور اس کی بشریت کی کمزوریاں ظاہر نہ ہوں یا یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں اس طورپر آجائے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو.قرآن کریم نے استغفار کے معنے میں وسعت پیدا کرتے ہوئے اس کو ان معنوں میں بھی استعمال کیا ہے کہ جو گناہ انسان سے صادر ہو چکے ہوں ان کے بد نتائج اور ان کی سزا سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی جائے.چنانچہ قرآن کریم میں یہ لفظ اس مفہوم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اور یہ ادنیٰ لوگوں کے لئے ہے.کامل لوگوں کے لئے اس کا یہی مفہوم ہوتا ہے کہ قوم کی اصلاح کرتے ہوئے اگر کوئی امر نظر انداز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کردے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کرنے کا مطلب سورۃ نصر کی زیر تفسیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے ہمارے رسول! اِسْتَغْفِرْہُ.اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو.اسی طرح قرآن کریم میں بعض مقامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں کہ اپنے ذنب کے لئے استغفار کرو.ایسے مقامات کو پڑھتے وقت یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ استغفار کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کن معنوں میں استعمال ہواہے.کیاان معنوں میں کہ آپؐسے کوئی گناہ سرزد ہواتھا اور پھر آپؐکو حکم ہوا کہ آپؐاس کی سزا سے بچائے جانے کی دعا کریں یا کسی اور معنے میں؟
Page 336
عیسائی صاحبان بھی ہمیشہ اس قسم کی آیات کو لے کر جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوا ستغفار کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں پر اعتراض کرتے چلے آئے ہیں کہ دیکھو تمہارا رسول گناہ گار تھا تبھی تو ان کو استغفار کا حکم دیا گیا.اور اس کے بعد وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ مسیح علیہ السلام کے لئے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا اس لئے وہ گناہوں سے پاک تھے.(A Comprehensive commentary on Quran by Wherry vol.4 p.292) اس اعتراض کے جواب میں مسلمانوں کو بڑی دقت پیش آئی اور گو انہوں نے جواب دینے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے اس کا جواب دینے میں وہ کامیاب نہیں ہوسکے.اور یہی وجہ تھی کہ ہزار ہا مسلمان عیسائی بن گئے.اور تو اور سادات میں سے بھی بعض نے بپتسمہ لے لیا.غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لفظ استغفار کے استعمال سے عیسائیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور بجائے اس کے کہ مسلمان عیسائیوں کو جواب دیتے وہ خود ان کے دھوکہ میں آگئے.ان آیات کو جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے حل کرنے کے لئے یہ امراچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہدایت اور راہنمائی کے لئے آئے تھے.اور اس دنیا میں اس لئے مبعوث کئے گئے تھے کہ تاگمراہ اور بے دین لوگوں کو باخدا انسان بنائیں اور تا گناہوں اور بدیوں میں گرفتار شدہ انسانوں کو پاک و صاف کریں.اور آپؐکا درجہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے.قُلْ اِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْکُمُ اللّٰہُ ( اٰل عمران:۳۲).اے ہمارے رسول! تم یہ بات لوگوں کو اچھی طرح سنا دو کہ اگر وہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ تیری اتباع کریں.اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بن جائیں گے.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰہِ اُسْوَۃٌ حَسَنَۃٌ( الاحزاب:۲۲) کہ اے مسلمانو! اس رسول میں تمہارے لئے ایک نیک نمونہ ہے.اگر تم خدا کے حضورمقبول بننا چاہتے ہو اور اگر تم خدا سے تعلق پیدا کرنا پسند کرتے ہوتو اس کا آسان طریق یہ ہے کہ اس رسول کے اقوال، افعال اور حرکات و سکنا ت کی پیروی کرو.کیونکہ آپؐکے اقوال و افعال خدا تعالیٰ کے اقوال و افعال ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے آپؐکے متعلق مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (الانفال:۱۸) کہہ کر آپؐکے کنکر پھینکنے کو اللہ تعالیٰ کا کنکر پھینکنا قرار دیا ہے.پھر آپؐکے متعلق یہ بھی فرمایا کہ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ( النجم:۴،۵) یعنی یہ نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی بات کہتا ہے جو خدا تعالیٰ اس کو بذریعہ وحی حکم دیتا ہے.پس وہ شخص جس کی اتباع سے انسان خدا
Page 337
سے ملتا ہی نہیں بلکہ اس کا محبوب بن جاتا ہے اور وہ شخص جو دنیا کے لئے ایک نمونہ تھا اور جس کے اقوال و افعال خدا کے اقوال وافعال تھے اس کا استغفار ان معنوں میں نہیں ہو سکتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہواتھا اور اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی سزا سے بچا لے.کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو سکتا تھا تو خدا تعالیٰ نے اس کی اتباع کا کیوں حکم دیا اور اسے دنیا کے لئے نمونہ کیوں قرار دیا؟ پس آپؐکو نمونہ قرار دینے کے معنے ہی یہ ہیں کہ آپؐہر ایک بدی اور گناہ سے پاک تھے.گویا آپؐکا استغفار گناہوں کی سزا سے بچنے کے لئے نہ تھا بلکہ کسی اور معنے میں تھا.اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کون سے معنے ہیں جن کو ادا کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے.سوجاننا چاہیے کہ زیر تفسیر سورۃ کی ابتدائی دوآیات میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی مسلمانوں کی نصرت کا سلسلہ جاری رہے گا اور فتوحات کے دروازے ان کے لئے کھول دئیے جائیں گے.اور قومیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح برکت پائیں گی جس طرح آپ کی زندگی میں لوگوں نے برکت پائی تھی.گویا ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آئندہ زمانہ میں ہزاروں ہزار لوگ اسلام میں ایک وقت میں داخل ہوا کریں گے اور یہ ظاہر ہے کہ جب کسی قوم کو فتح حاصل ہوتی ہے اور مفتوح قوم کے ساتھ فاتح قوم کے تعلقات قائم ہوتے ہیں تو ان میں جو بدیاں اور بُرائیاں ہوتی ہیں وہ فاتح قوم میں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں.یہی وجہ ہے کہ فاتح قوم جن ملکوں سے گذرتی ہے ان کے عیش و عشرت کے جذبات اپنے اندر لے لیتی ہے اور چونکہ عظیم الشان فتوحات کے بعداس قدر آبادی کے ساتھ فاتح قوم کا تعلق ہوتا ہے جو فاتح سے بھی تعداد میں زیادہ ہوتی ہے.اس لئے اس کو فوراً تعلیم دینا اور اپنی سطح پر لانا مشکل ہوتا ہے.اور جب فاتح قوم کے افراد مفتوح قوم میں ملتے ہیں تو بجائے اس کو اخلاقی طور پر نفع پہنچانے کے خود اس کے بدا ثرات سے متاثر ہوجاتے ہیں.جس کا نتیجہ رفتہ رفتہ نہایت خطرناک ہوتا ہے اور درحقیقت جس وقت کوئی قوم ترقی کرتی اور کثرت سے پھیلتی ہے.وہی زمانہ اس کے تنزل اور انحطاط کابھی ہوتا ہے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان فتوحات کی خبر کو معلوم کر کے طبعی طور پر متفکر ہو سکتے تھے کہ ان فتوحات کے ساتھ ساتھ کہیں مسلمانوں میں انحطاط تو شروع نہ ہو جائے گا اور وہ لوگ جو اسلام میں نئے داخل ہوں گے ان کی پوری طرح تربیت کا کیا سامان ہو گا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل استاد اور نفوس کا تزکیہ کرنے والا اور کامل راہنما ان کو میسر نہ ہوگا.پس ان خیالات کے جواب کے طورپر اللہ تعالیٰ نے اِسْتَغْفِرْہُ کے الفاظ نازل فرمائے اور بتایا کہ اے محمدرسول اللہ ! جب
Page 338
تک آپ دنیا میں رہے آپؐنے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور تربیت اور تزکیۂ نفوس کا کام کرتے رہے.لیکن جب آپ ہمارے پاس آجائیں گے.تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ خود امّتِ محمدیہ کا کفیل ہو جائے گا.ایسی صورت میںآپ کو فکر کی کیا ضرورت ہے.ہاں آپ وہ کام کریں جو آپ کی استطاعت میں ہے اور وہ یہ کہ آپؐدعاؤں میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ وہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی حفاظت کرے اور ان کی نصرت کرتا رہے بلکہ اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کی بھی خود ہی تربیت کا سامان کرے.اور ایسی صورت پیدا کردے کہ تما م مسلمان ٹھوکر اور غلطیوں سے بچتے رہیں.اور اگر کبھی کوئی رخنہ پیدا بھی ہو تو اس کی اصلاح کا سامان خدا تعالیٰ پیدا کرتا رہے.گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لئے استغفار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اپنی امّت کے لوگو ں کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کی اُمّت کی حفاظت فرمائے اور ان میں کوئی روحانی طور پر رخنہ نہ پڑے اور اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو اس کی اصلاح کا سامان پیدا ہو جائے.چنانچہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے مطابق دعا کرنی شروع کردی(درمنثور زیر آیت ھذا) اور واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشااور آپ کی وفات کے بعد جس قدر فتنے پیدا ہوئے ان کی اصلاح کر دی گئی.اور آئندہ ایسا انتظام کر دیا گیا کہ ہرفتنے کے پیدا ہونے پر اس کی اصلاح ہو جائے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی وفات پر جب بعض قبائلِ عرب مرتد ہو گئے اور بعض نے زکوٰۃ دینے سے انکار کردیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کا ایسا سدِّ باب کیا جس کی نظیر ملنی مشکل ہے اور پھر سے اسلام صحیح شکل میں قائم ہو گیا.اگر اس وقت اس فتنہ کو دبایا نہ جاتا تو اسلام کی صحیح شکل کا قائم رہنا مشکل امر تھا.اسی طرح اسلام کی فتوحات کے زمانہ میں جب کثرت سے عیسائی لوگ مسلمان ہوئے تو وہ اپنے ساتھ حیاتِ مسیح اور مسیحؑ کے بے گناہ ہونے اور باقی تمام انسانوں کے ( جن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آجاتے ہیں ) خطاکار ہونے کا عقیدہ بھی لے آئے اور وہ اتنا پھیلاکہ اس غلط فہمی کی وجہ سے عیسائیت کو اسلام پر حملہ کرنے کا موقع مِل گیا اور مسلمان اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہونے شروع ہو گئے.آخر اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے استیصال کے لئے اور اُمّت کی حفاظت کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چودہ سو سال بعد کھڑا کر دیا اور آپ کے ذریعہ اسلام کو ایسے مقام پر کھڑا کردیا کہ کجا وہ حالت کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا تھا اور مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے تھے اور کجا یہ حالت پیدا ہو گئی کہ تمام مذاہب میدان سے بھاگ گئے اور اسلام عیسائیت پر حملہ آور ہو گیا اور غیر مذاہب کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو نے شروع ہو گئے اور وہ
Page 339
دن دور نہیں جبکہ ہرشخص اسلام کے مادی غلبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اسلام کا ضعف اس کی طاقت میں تبدیل ہو جائے گا.پس یہ سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار اور دعا کا نتیجہ ہے.اب ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ جن آیات میں استغفار کے ساتھ ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے.کیونکہ ذنب کے معنے لغت میں جُرم کے لکھے ہیں.اور اس لحاظ سے اِسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ کے معنے یہ بنیں گے کہ اے محمد رسول اللہ !اپنے جُرم کے لئے آپ استغفار کریں.اس بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ اس آیت کی تفسیر کے شروع میں اصولی طور پر لکھا جا چکا ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم الشان انسان ہیں جن کی اتباع سے انسان خدا سے ملتا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے.اور پھر یہ کہ آپ دنیا کے لئے نمونہ ہیں اور آپ کے اقوال و افعال خدا کے اقوال و افعال ہیں.پس آپؐکے متعلق یہ تصوّر ہی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم نے کہیں یہ کہا ہو کہ آپؐگناہ گار ہیں.کیونکہ آپؐتو دنیا کو گناہ سے چھڑانے کے لئے آئے تھے.اگر آپؐخود ہی گناہ گار تھے تو دنیا کو گناہ سے کیسے آزاد کر واسکتے تھے.پس وہ آیات جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنے قرآن کریم کے بیان کی روشنی میں یہ نہیں کئے جا سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گناہ کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا تھا بلکہ اس کے اور ہی معنے ہیں.اب ان معنوں کو معلوم کرنے کے لئے ہم ان آیات پر یکجائی نظر کرتے ہیں جن میں ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے.چنانچہ وہ آیات حسب ذیل ہیں :.۱.اللہ تعالیٰ سورۃ مومن میں فرماتا ہے.فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ الْاِبْكَارِ (المؤمن :۵۶) ۲.سورۃ محمدؐ میں یوں آیا ہے.فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ١ؕ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ (محمّد:۲۰) ۳.تیسری آیت جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا لفظ استعمال ہواہے وہ سورۃ فتح کی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا.لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا( الفتح:۲،۳) ان آیات میں اور سورۃ محمدؐ اور مومن کی آیات میں لفظ ذنب کے استعمال میں ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ سورۃ محمد ؐ اور مؤمن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ یعنی اپنے ذنب کے لئے
Page 340
استغفار کرو.اور سورۃ فتح کی آیات میں غفر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے.اور فرمایا ہے لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے پہلے اور پچھلے ذنب پر مغفرت کردی ہے.ان آیا ت کے حل کے لئے سب سے پہلے ہم لغت کی طرف توجہ کرتے ہیں.لغت میں غفر کے معنے ڈھانکنے کے ہیں.اور ذَنَبَہٗ ذَنْبًا کے معنے ہوتے ہیں.تَلَاہُ فَلَمْ یُفَارِقْ اِثْرَہٗ کہ اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کی اتباع اور قدم بقدم چلنے کو ترک نہ کیا اور ذَنَّبَ الْعَـمَامَۃَ کے معنے ہوتے ہیں.اَفْضَلَ مِنْـھَا شَیْئًا وَاَرْخَاہُ کہ پگڑی باندھتے وقت اس کا ایک زائد حصہ جو سر پر لپیٹا نہ جا سکتا تھا اس کو لٹکادیا( اقرب).پس ذَنْب کے معنے ہوئے پیچھے آنا یا زائد چیز.اور غَفَرَ ذَنْبَ کے معنے ہوئے زائد چیز کا ڈھانپ دینا یا پیچھے آنے والے واقعات کی خرابیوں کا ڈھانپ دینا.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذَنْب کے لئے اِسْتِغْفَار کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ آپ یہ دعا کریں کہ نبوت کے کام کے وہ بوجھ جو بشری طاقت سے زائد ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اٹھانے کی طاقت عطاکردے.یا آپ کے بعد آنے والے واقعات کی خرابیوں پر پردہ ڈال دے.اب ہم سورۃ مؤمن، سورۃ محمدؐ اور سورۃ فتح کی ان آیات پر جن میں ذنب کا لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا گیا ہے جب غور کرتے ہیں تو ایک ایسی عجیب بات معلوم ہوتی ہے.جو ان آیات کے مضمون کو اس طرح حل کردیتی ہے کہ سب اعتراض دور ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہ ان سب جگہوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ہلاک ہونے اور آپ کی فتح کا ذکر ہے.چنانچہ پہلا مقام سورۃ مؤمن کا ہے اور یہ سورۃ مکی ہے اور اس میں آتا ہے کہ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ.یعنی اے رسول اللہ !آپ دشمنوں کی ایذائوں پر صبر کریں اور اس دن کا انتظار کریں جب آپ کا غلبہ ہو گا اور یہ ایذا دینے والے شرمندہ ہوں گے.اور یہ یاد رکھیں کہ یہ غلبہ کا وعدہ پورا ہوکر رہے گا اور مکہ بھی آپ کو ملے گا اور آپ اپنے ذنب کے لئے استغفار کریں.اس آیت سے پہلے مندرجہ ذیل آیات ہیں.اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ.يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ.وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَ اَوْرَثْنَا بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ.هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ.(المؤمن:۵۲تا۵۵) یہ آیات مکہ میں نازل ہوئی تھیں جب مسلمان بہت تکلیف اور دکھ میں تھے.اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے مسلمانو! گھبرائو نہیں اور یاد رکھو کہ ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کی جو ان پر ایمان لاتے ہیں
Page 341
اسی دنیا میں مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے جب فیصلہ کے لئے گواہ اپنی گواہیاں دینے کے لئے آکھڑے ہوں گے.وہ ایسا دن ہوگا جبکہ نافرمانوں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی او ران کے لئے خدا سے دوری ہو گی اور انہیں رہنے کو بہت برا گھر ملے گا.یاد رکھو ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو تورات کا وارث کیا جس میں لوگوں کے لئے ہدایت اور نصیحت تھی یعنی جس طرح بنی اسرائیل تورات کی برکت سے ارضِ مقدسہ کے وارث ہوگئے اور خدا کی نعمتیں ان کو مل گئیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی مکمل کتاب ملے گی اوردنیا پر ظاہری غلبہ بھی حاصل ہو جائے گا اور مکہ جو ان کا مقدس مقام ہے اور جو اس وقت مخالفوں کے قبضہ میں ہے وہ بھی ان کو مل جائے گا.اس غلبہ کی پیشگوئی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ کہ اے رسول ! جلدی نہ کرو کہ یہ غلبہ کا وعدہ کب آئے گا بلکہ صبر سے کام لو.یقیناً یہ وعدہ پورا ہوکر رہے گا اور اپنے ذنب کے لئے استغفار کرو.غرض پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہلاکت کی خبر دی اور پھر غلبہ اور فتح مکہ کی خبردی اور استغفار کا حکم دیا.دوسری جگہ جہاں استغفار کا حکم ہے وہ سورۃ محمدؐ کی یہ آیت ہے.فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ.اس سے پہلے یہ آیت ہے فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً١ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا١ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ.سورۃ محمدؐ کا سارا مضمون مخالفینِ اسلام کی تباہی کے ذکر میں ہے اور یہ بتایاگیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائیں گے اور اسلام کو فتح ہو گی.اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً کہ مخالفینِ اسلام تو بس اس گھڑی کے منتظر ہیں جس میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون او راس سے پہلے پہلے اسلام کے دلائل پر غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم اس وقت جب معاملہ کھل جائے گا ایمان لے آئیں گے.لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ فتح مکہ کی گھڑی اچانک آجائے گی.ہاں یادرکھو اس کے قریب آنے کی علامات ظاہر ہو چکی ہیں.پھر جب وہ گھڑی آپہنچے گی ان کا ایمان لانا ان کو کیافائدہ دے سکتا ہے.پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ! یہ امر یاد رکھو کہ صرف قادر خدا ایک ہی ہے اسی کے اشارے پر ہر ایک چیز حرکت کرتی ہے.پس جب وقت آجائے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتریں گے اور لوگوں کے دلوں کو تمہاری طرف مائل کردیں گے اور لوگوں کے لئے اسلام میں
Page 342
داخل ہونے کا راستہ کھل جائے گا.پس ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنا چاہیے نہ صرف اپنے لئے بلکہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات سے بخوبی واقف ہے.غرض ان آیات میں بھی پہلے دشمنوں کی تباہی کا ذکر ہے اور پھر مسلمانوں کی کامیابی اور اس کے بعد استغفار کا حکم ہے.تیسری جگہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذنب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تیرے ذنب پر پردہ ڈال دیا ہے.وہ سورۃ فتح کی ابتدائی آیات ہیں.ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا.لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ وَ يُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا.وَّ يَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا.یعنی اے نبی ! ہم تجھے ایک ایسی کھلی فتح عطاکریں گے کہ جس کے بعد ہرایک پر واضح ہوجائے گا کہ دین اسلام سچا دین ہے.اور تم صراط مستقیم پر تھے اور اس فتح کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طرف تم پر فتح سے پہلے ایمان لانے والوں کی تربیت ہو کر ان کے نقائص دور ہو جائیں گے اور تمہاری بشری کمزوریوں کی وجہ سے ان کی تربیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ دور کردی جائے گی اور فتح کے بعد جو لوگ اسلام میںداخل ہوں گے ان کی تربیت میں اگر تمہاری بشری کمزوریوں کی وجہ سے کوئی نقص رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کردے گا اور تمہاری دعائوں کے نتیجہ میں تم پر نعمت کو مکمل کردے گا.یعنی مسلمانوں میں ایسے لوگ بار بار پیدا ہوتے رہیں گے جو اصلاحِ امّت کا کام سر انجام دیں گے اور اس کی خرابیوں کو دور کر کے صحیح مقام پران کو قائم رکھیں گے اور دنیا وی لحاظ سے بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی.اور اللہ تعالیٰ ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کردے گاجس سے وہ خدا تعالیٰ کے انعامات کے مورد ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی نصرت کرے گا کہ کوئی مانع اور مزاحم نہ ہو سکے گا.ان آیات میں بھی پہلے فتح و نصرت کا ذکر ہے اور دشمنوں کی ہلاکت کی پیشگوئی کی گئی ہے اور اس کے بعد ذنب پر مغفرت کر دینے کا ذکر کیا گیا ہے.غرض ان تمام آیات کو دیکھ کر بالطبع یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور آپ کے دشمنوں کی مغلوبیت کے ساتھ وہ کون سی بات متعلق ہے جس کے لئے استغفار کا حکم ہے.یاوہ کون سی بات ہے جس کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے اس پر مغفرت کردی ہے.سوجاننا چاہیے کہ نبی باوجود نبی ہونے کے پھر انسان ہی ہوتا ہے اور انسان کے تما م کام خواہ کسی حدتک وسیع ہوں محدود ہی ہوتے ہیں.ایک استاد خواہ کتنا ہی لائق ہو اور ایک
Page 343
وقت میں تیس چالیس نہیں بلکہ سو سَوا سو لڑکوں کو بھی پڑھا سکتا ہو.اگر اس کے پاس ہزار دو ہزار لڑکے لے آئیں تو نہیں پڑھاسکے گا.رسول بھی استاد ہی ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آتا ہے.یَتْلُوْا عَلَیْھِمْ اٰیٰتِہٖ وَیُزَکِّیْھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ.( اٰل عمران:۱۶۵) کہ اس رسول کاکام یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو سنائے.کتاب کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے اوراحکام کا فلسفہ سکھائے.غرض نبی ایک استاد ہوتا ہے اس کا کام تعلیم دینا ہوتا ہے اس لئے وہ تھوڑے لوگوں کو ہی دے سکتا ہے کیونکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو سبق دینا اور پھر یا د بھی کروا دینا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا.پس جب کسی کے سامنے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی جماعت سبق لینے کے لئے کھڑی ہو تو ضرور ہو گا کہ اس کی تعلیم میں نقص رہ جائے اور لوگ پوری طرح علم نہ حاصل کر سکیں.یا یہ ہوگا کہ بعض تو پڑھ جائیں گے اور بعض کی تعلیم ناقص رہ جائے گی اور بعض بالکل جاہل کے جاہل ہی رہ جائیں گے اور کوئی تعلیم حاصل نہ کرسکیں گے.پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کی خبردی اور بتایا گیا کہ مکہ فتح ہوگا اور اس کے نتیجہ میں بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوں گے تو آپؐکے دل میں جو بڑا ہی پاک دل تھا یہ گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ ان تھوڑے سے لوگوں کو تو میں اچھی طرح تعلیم دے لیتا تھا، قرآن کریم سکھاسکتا تھا.لیکن یہ جو لاکھوں انسان اسلام میں داخل ہوں گے ان کو میں کس طرح تعلیم دوں گا.اور مجھ میں جو بوجہ بشریت کے یہ کمزوری ہے کہ اتنے کثیر لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا اس کا کیاعلاج ہوگا.اس کا جواب خدا تعالیٰ نے یہ دیا کہ اس میں شک نہیں کہ جب فتح ہوگی اور نئے نئے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوں گے توان میں بہت سی کمزوریاں ہوں گی.اور یہ بھی سچ ہے کہ وہ سب کے سب آپ سے تعلیم نہیں پا سکتے.مگر ان کو تعلیم دلانے کا یہ علاج ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے خدا مجھ میں بشریت کے لحاظ سے یہ کمزوری ہے کہ اتنے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا تُومیری اس کمزوری کو ڈھانپ دے اور وہ اس طرح کہ ان سب لوگوں کو خود ہی تعلیم دےدے اور خود ہی ان کو پاک کردے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اِسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ کے الفاظ کہہ کر اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اسلام میں کثرت سے داخل ہونے والے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لئے آپ خدا تعالیٰ سے دعاکریں اور التجا کریں کہ اب لوگوں کے کثرت سے آنے کی وجہ سے جو بد نتائج نکل سکتے ہیں ان سے آپ ہی بچائیے.اوران کو خود ہی دور کر دیجئے.اور یہ ظاہر ہے کہ آپ کا لاکھوں انسانوں کو ایک ہی وقت میں پوری تعلیم نہ دے سکنا کوئی گناہ نہیں.بلکہ بشری کمزوری کا نتیجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ
Page 344
آپ کے متعلق ذَنْب کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن جَنَاحٌ، اِثْمٌ یا جُرْمٌ کا لفظ استعمال نہیں ہوا.گناہ اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے باوجود اس کے حکم کی فرمانبرداری نہ کی جائے اور وہ بات جس کی خدا تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہی نہ دی جائے اس کا نہ کر سکنا گناہ نہیں ہوتا.بلکہ وہ بشری کمزوری کہلاتی ہے مثلاً ایک شخص بیمار ہوجاتا ہے تو یہ اس کا گناہ نہیں بلکہ ایک کمزوری ہے جو بشریت کی وجہ سے اسے لاحق ہوئی.تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گناہ نہ تھا کہ آپؐاس قدر زیادہ لوگوں کو پڑھا نہ سکتے تھے بلکہ خدا تعالیٰ نے آپؐکو بنایا ہی ایساتھا اور آپؐکے ساتھ یہ ایسی بات لگی ہوئی تھی جو آپؐکی طاقت سے بالا تھی.اس لئے آپؐکو بتایا گیا کہ ایمان لانے والوں کی کثرت کی وجہ سے جو نقص ان کی تعلیم میں رہ جائے گا اس کے دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.پس وہ تمام آیات جن میں آپؐکے لئے وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گناہ کا اظہار مقصود نہیں ہے بلکہ بشری کمزوری کے بدنتائج سے بچنے کی آپؐکو راہ بتائی گئی ہے.اور بتایا گیا ہے کہ وہ بوجھ جو آپؐپر پڑنے والا ہے اور آپ کی طاقت سے زائد ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعاکریں کہ اس کو اٹھانے اور ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کرنے کی توفیق ملے.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت زیادہ عرصہ نہ رہ سکے تھے.ابتلائوں اور فتنوں کے وقت ان کا ایمان بھی خراب نہ ہوا اور وہ اسلام جیسی نعمت سے محروم نہ ہوئے.گو آپؐکی وفات پر کچھ لوگ مرتد ہوئے مگر جلدی ہی واپس آگئے.اور ان فسادوں میں شامل نہ ہوئے جو اسلام کو تباہ کرنے کے لئے شریروں اور مفسدوں نے برپا کئے تھے.چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جو عظیم الشان فساد ہوااس میں عراق، مصر، کوفہ اور بصرہ کے لوگ تو شامل ہوگئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایمان لائے تھے لیکن یمن، حجاز اور نجد کے لوگ شامل نہ ہوئے.یہ وہ ملک تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں فتح ہوئے تھے.پس اللہ تعالیٰ نے ان مُلکوں کے لوگوں کی جو آپؐکے زمانہ میں اسلام لائے تھے برائیاں اور کمزوریاں دور کردی تھیں.لوگ تو کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کا زور اور طاقت تھی کہ شام کے لوگ اس فتنہ میں شامل نہ ہوئے.لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی اور دعا کا اثر تھا کہ شام کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں اٹھے.کیونکہ گویہ ملک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فتح نہ ہوالیکن آپؐنے اس پر بھی چڑھائی کی تھی جس کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ توبہ میں ان تین صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے
Page 345
آیا ہے جو اس سفر میں شامل نہ ہوئے تھے.پس شام کا اس فتنہ میں شامل نہ ہونا امیر معاویہ کی دانائی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس لئے تھاکہ وہاں اسلام کا بیج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بویا گیا اور اس سرزمین میں آپؐنے قدم مبارک ڈالاتھا.پس خدا تعالیٰ نے آپؐکی دعائوں میں اس ملک کو بھی شامل کر لیا.اس عظیم الشان فتنہ میں اس قدر صحابہ میں سے صرف تین صحابہ کے شامل ہونے کا پتہ لگتا ہے.اور ان کی نسبت بھی ثابت ہے کہ صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے شامل ہوگئے تھے اور بعد میں توبہ کر لی تھی.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی.اس لئے جہاں آپؐکی فتح کا ذکر آیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام میں کثرت سے لوگ داخل ہونے والے ہیں وہاں ساتھ ہی استغفار کا حکم بھی آیا ہے.جو آپؐکو اس طرف متوجہ کرنے کے لئے تھا کہ ہم آپ کو غلبہ اور عزت دینے والے ہیں اور بے شما رلوگ آپ کے ساتھ شامل ہونے والے ہیں.پس یادرکھیں کہ جب آپ کے پاس بہت سے شاگرد ہو جائیں تو آپ خدا تعالیٰ کے حضور گرجائیں اور عرض کریں کہ الٰہی اب کام انسانی طاقت سے بڑھتا جاتا ہے.آپ خود ہی ان نوواردوں کی اصلاح کر دیجئے.ہم آپ کی دعا قبول کریں گے اور ان کی اصلاح کردیں گے اور ان کی کمزوریاں اور بدیاں دور کر کے ان کو پاک کردیں گے.پس قرآن کریم کی وہ آیات جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ذنب کے لئے استغفار کرنا چاہیے.اس سے یہ ہر گز مراد نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اوراس کے لئے آپ کو استغفار کرنا چاہیے بلکہ اس سے صرف یہ مراد ہے کہ فتوحات کی وجہ سے اور اسلام میں لوگوں کے کثرت سے داخل ہونے کی وجہ سے جو تربیت کا کام بڑھنے والا ہے اور وہ آپ کی طاقتوں سے زیادہ ہے.اللہ تعالیٰ اس کو باحسن وجوہ سرانجام دینے کی طاقت عطاکرے اور اگر اس میں کوئی کمزوری رہ جائے تو اس پر پردہ ڈال دے اور اس کی اصلاح اس طور پر کردے کہ کوئی برا نتیجہ پیدا نہ ہو.اور چونکہ یہ نومسلموں کی تربیت کا کام صحابہ اور صحابیات نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے ماتحت کرنا تھا.اس لئے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ محمدؐ کی آیات میں یہ بھی فرما دیا کہ نہ صرف اپنے لئے بلکہ آپ کے ماتحت جو مربی کام کرنے والے ہیں ان کے لئے بھی دعا کردیں کہ وہ صحیح رنگ میں تربیت کر سکیں اور اگر ان کی تربیت میںکوئی نقص رہ جائے تو اس کا بد نتیجہ نہ نکلے بلکہ اس کی بھی پردہ پوشی ہوجائے.
Page 346
خلاصہ کلام یہ کہ سورۃ نصر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اِستَغْفِرہُ کا حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ فتوحات کے نتیجے میں جوخرابیاں اُمّت محمدیہ میں پیدا ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کی اصلاح کا انتظام فرماوے.اور وہ آیات جہاں اِسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ کے الفاظ کہے گئے ہیں ان میں یہ حکم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ کے زمانہ میں جو فتوحات ہوں گی اور جن کے نتیجہ میں کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی تربیت پوری طرح کرنے کی توفیق دے اور اگر تربیت میں کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کے نتیجہ میں جو خرابی پیداہو سکتی ہے اس کے بد نتائج سے بچا لے.اِنَّہٗ کَانَ تَوَّابًا:.تَابَ کے معنے ہوتے ہیں فضل کے ساتھ رجوع کیا اور توّاب مبالغہ کا صیغہ ہے اس لئے اس کے معنے ہوں گے باربار فضل کے ساتھ رجوع کرنے والا.گویا اس حصۂ آیت میں اس مضمون کو ادا کیا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ ! اگر آپ دعائوں میں لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائوں کو ضرور سنے گا اور اپنے فضل کے ساتھ آپ کی قوم پر بار بار رجوع کرے گا.نبوت، صدیقیت، شہیدیت اور صالحیت چار روحانی انعام ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان انعاموں کا ملنا خدا تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ فَاُولٰٓىِٕكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ۠ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصّٰلِحِيْنَ١ۚ وَ حَسُنَ اُولٰٓىِٕكَ رَفِيْقًا.ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ١ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا.( النسآء:۷۰،۷۱) یعنی جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے زمرہ میں شامل ہو جائے گا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالح اور ان مقامات کا ملنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بوجہ علیم ہونے کے پوری طرح جانتا ہے کہ کون ان فضلوں کا مورد ہونے کا اہل ہے.اِنَّہٗ کَانَ تَوَّابًا میں اسلام کی حفاظت کی پیشگوئی پس اِنَّہٗ کَانَ تَوَّابًا کے الفاظ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ جب بھی آپ کی قوم کو حفاظت کی ضرورت ہوگی جب بھی کسی اصلاح کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور اصلاح کے ذرائع پیدا کردے گا اور اس خرابی کے مناسبِ حال شخص پیدا کر دے گا.چنانچہ واقعات بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی گئی اور امّت میں جب بھی کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اس کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب حال شخص کھڑا کردیا.چنانچہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے جب
Page 347
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت بڑے بڑے صحابہ گھبرا گئے.حتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زبردست شخص بھی گھبرا گیا(بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قول النبی لو کنت متخذًا خلیلًا).اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کے مقام پر کھڑا کردیا اور تمام مسلمان ایک ہاتھ پر جمع ہوگئے.اور جتنے فتنے اس وقت کھڑے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے کی قوت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی گئی.باوجود اس کے کہ آپ کی طبیعت نرم تھی لیکن آپ نے فتنوں کو دبانے کے لئے جو کام کیا اس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے.پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعائوں کے نتیجہ میںتھی جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کیں.پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کردیا.چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور ایرانیوں اور شامیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہورہی تھی اس لئے آپ کی وفات کو بے وقت سمجھا گیا(تاریخ ابی الفدا ذکر وفات ابی بکر) لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت پر متمکن ہوتے ہی ایسی راہنمائی کی کہ مصر، شام اور فلسطین کے سارے علاقے مسلمانوں کے ماتحت آگئے اور قیصرو کسریٰ کی ساری طاقتیں ختم ہوگئیں.اور ایک طرف مسلمانوں کی ایک مستحکم سلطنت قائم ہوگئی اور دوسری طرف مسلمان ایک ہاتھ پر اکٹھے رہے اوران میں کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی.بلکہ آپ کی خلافت میں اسلام کا وہ رعب و دبدبہ قائم ہوا کہ مسلمان بڑے بڑے بادشاہوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے.پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں کا دوسرا اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وجود میں ظاہر ہوا.پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے وجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں کا نتیجہ تھے.پھر حضرت عمربن عبدالعزیز اور مجدّدینِ اُمّت جو مختلف ممالک اور مختلف زمانوں میں اسلام کی حفاظت اور اسلام کی صحیح صورت کو قائم رکھنے کے لئے کھڑے ہوئے سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں کی بدولت ہی تھے.اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال بعد جب ایک طرف آپؐکےماننے والے اسلام کو چھوڑ بیٹھے اور اس پر عمل کرنا ترک کردیا اور دوسری طرف مغربی اقوام نے اسلام پر ہلّہ بول دیا اور چاہا کہ اسلام کا نام تک مٹا دیا جائے.ایسی نازک حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث کردیا اور آپؑکے ذریعہ مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت قائم کردی جو ایک طرف صحیح اسلام کا نمونہ تھی او ردوسری طرف وہ اسلام کے لئے اپنے اموال اور اپنی جانو ںکو قربان
Page 348
کرنے والے تھے.اور اس طرح اسلام از سر نو زندہ ہو گیا.چنانچہ کجا تو یہ حالت تھی کہ سمندر پار سے عیسائیوں کے پادری مسلمانوں کے مختلف ممالک میں اسلام پر حملے کر رہے تھے اور کجا یہ حالت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں نے ان کے ممالک میں پہنچ کر ان پر حملہ شروع کر دیا اور یکے بعد دیگرے مخالفین میں سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشّاق پیدا ہونے شروع ہو گئے اور اب یہ بات نظر آرہی ہے کہ وہ دن جلد ہی آنے والا ہے جبکہ تمام مغربی اقوام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گی اور ایک ہی رسول ہوگا او رایک ہی شریعت اور خدا تعالیٰ کی بادشاہت جس طرح آسمان پر ہے زمین پر بھی قائم ہوجائے گی.بہر حال اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں کو سنے گا اور باربار اپنے فضل کے ساتھ آپ کی قوم پر رجوع کرے گا وہ پوری شان کے ساتھ پوراہوا ہے اور پورا ہوتا رہے گا.کیونکہ اسلام قیامت تک کے لئے ہے اور خدا کے وعدے بھی قیامت تک پورے ہوتے رہیں گے.انشاء اللہ.روایات میں آتا ہے کہ جب سورۃ نصر نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس سے اطلاع دی تو آپ نے فرمایا لَیَخْرُجَنَّ مِنْہُ اَفْوَاجًا کَمَا دَخَلُوْا فِیْہِ اَفْوَاجًا( فتح القدیر تفسیر سورۃ النصر آیت ۱) کہ اب تو اسلام میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہورہے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جبکہ مسلمان گروہ در گروہ اسلام کو خیر باد کہنے لگ جائیں گے اور اسلام کے حلقہ سے نکل جائیں گے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ سَو فی صدی پورا ہوا ہے.چنانچہ اس زمانہ میں جب عیسائیت نے اسلام پر حملہ کیا لوگ کثرت سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گئے تھے.اور اسی طرح سے دوسری تحریکیں جو اسلام کے خلاف چلیں ان کا شکار ہوگئے تھے.پس اسلام کا موجودہ تنزّل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کابیّن ثبوت ہے.کیونکہ ایسے وقت میں جب کہ اسلام دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا تھا.اور اس کے تنزّل کاخیال بھی نہیں آسکتا تھا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جبکہ اسلام کے ماننے والے اس کو خیر باد کہہ دیں گے.اور گروہ درگروہ اسلام سے نکل کھڑے ہوں گے صرف اور صرف خدائے علّام الغیوب کے علم کی بنا پر ہی ہو سکتا تھا.پس جہاں خدا تعالیٰ کی یہ بات پوری ہوئی ہے وہاں دوسری بات بھی پوری ہو گی جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوائی کہ دوبارہ اسلام زندہ کیا جائے گا.اور مسیح موعود کی بعثت کے ذریعہ سے اسلام کا سورج پھر وسطِ آسمان میں چمکے گا.اور تمام قومیں اسلام میں داخل ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے گیت گائیں گی.پس
Page 349
جس طرح سے عالم الغیب خدا کی باتیں پہلے پوری ہوئی ہیں، اب بھی پوری ہوں گی.وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ.روایات میں آتا ہے کہ سورۃ نصر کے نزول پر اللہ تعالیٰ کے حکم سَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّکَ وَاسْتَغْفِرْہُ کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائیہ کلمات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا کرتے تھے کہ سُبْـحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِـحَمْدِکَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ.( در منثور سورۃ النصر) یعنی اے اللہ میں تیری تسبیح کرتاہوں اور تیری ذات میں سب خوبیوں کے ہونے کا اقرار کرتاہوں اور تجھ سے بشری کمزوری پر پردہ پوشی چاہتاہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں.حضرت ام سلمہؓ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ دعا باربار کیوں پڑھتے ہیں.تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی قسم کی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا ہے اور پھر سورۃ نصر کی آیات پڑھیں.بہر حال اس روایت سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی اُمّت کے لئے کثرت سے دعائیں کیں تاآپ کی اُمّت راہِ راست پر قائم رہے اور جب کبھی اس میں کوئی خرابی پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو کھڑا کر دے جو اس خرابی کو دور کردیں اور یہ کہ خود اللہ تعالیٰ اُمّت محمدیہ کی تربیت کا انتظام کرتا رہے.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنی گئی اور اس کا نتیجہ جو کچھ نکلا وہ تاریخ کے اوراق بتا رہے ہیں اور قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا اور جب بھی اسلام کی حفاظت کا سوال پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کے سامان پیدا کردے گا.
Page 350
سُوْرَۃُ اللَّھَبِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ اللھب.یہ سورۃ مکّی ہے وَھِیَ سِتُّ اٰیَاتٍ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ اور اس کی بسم اللہ سمیت چھ آیات ہیں.سورۃ لہب مکّی ہے سورۃ اللّہب مکی سورۃ ہے اوراس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں.ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ اور ابن الزبیر سے روایت کی ہے کہ یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی.( فتح القدیر سورۃ اللّہب) تفسیر اتقان میں علامہ سیوطی نے جو ترتیب نزول مختلف راویوں سے بیان کی ہے اس میں سورۃ اللّہب کو پانچویں نمبر پر بیان کیا ہے یعنی ان کی تحقیقات میں سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی پھر نون والقلم پھر مزّمّل پھر مدّثّر پھر سورۃ اللّہب.(الاتقان النوع الاول فی معرفۃ المکی والمدنی ) گویا یہ سورۃ بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے.وہیری کے نزدیک اس سورۃ کا نزول نبوت کے پانچویں یا چھٹے سال ہواتھا.ترتیب و تعلق مضمون کے اعتبار سے سورۃ اللّہب قرآن کریم کی آخری سورۃ ہے.کیونکہ ہماری ترتیب کے لحاظ سے اس پر قرآن کریم کا مضمون ختم ہوجاتا ہے.اس کے بعد کی تین سورتوں میں قرآن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے.سورۃ لہب کا تعلق پہلی سورۃ سے اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی تھی کہ وہ فتوحات جو آپ کو ہورہی ہیں وہ آپ کی حیات تک محدود نہیں بلکہ ان فتوحات کے دروازے آپ کی وفات کے بعد بھی کھلے رہیں گے.یہاں تک کہ اسلام دنیا پر غالب آجائے گا.اور پھر یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جب بھی اسلام کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہو گی جو اس کی کشتی کو بھنور سے نکالے اور اس کا جھنڈا سر نگوں نہ ہونے دے.اللہ تعالیٰ اس وقت کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دے گا اور اُمّت محمدیہ کی دستگیری فرمائے گا.سورۃ لہب کا خلاصہ مضمون سورۂ لہب میں سورۃ نصر کے مضمون کو مکمل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتوحات کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اور اسلام
Page 351
غالب ہو جائے گا بلکہ اگر کسی نے اسلام کومٹانے کے لئے اس پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس حملہ آورکو تباہ کر دے گا نہ صرف اس کو بلکہ ان کو بھی جو اس حملہ آور کی تائید میں ہوں گے.ایسے لوگ جو اسلام کے خلاف حملہ آور ہونے والے تھے ان کو اس سورۃ میں ابو لہب کے نام سے پکارا ہے.اور ان کو جو ایسے لوگوں کی تائید میں ہوں گے بیوی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے.گویا ابو لہب سے مراد ائمہ کفر ہیں اوراس کی بیوی سے مراد ان کے اتباع.جیسا کہ آدم علیہ السلام کی بیوی سے مراد آدم کے اتباع بھی ہیں.گویا اس سورۃ میں سورۂ نصر میں بیان ہونے والے مضمون سے پیداشدہ ایک سوال کا جواب دیاگیا ہے اور وہ یہ کہ طبعی طور پر دل میں خیال آسکتا تھا کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتوحات کے دروازے کھل بھی گئے اور اسلام غالب بھی آگیا.لیکن پھر کسی وقت کوئی ایسا زبردست دشمن پیدا ہوگیا جس نے اسلام پرحملہ کر کے اس کے غلبہ کو ختم کردیا تو اس عارضی غلبہ کا کیا فائدہ؟ اس سوال کا جواب سورۂ لہب میں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اے محمد رسول اللہ ! یہ امر اچھی طرح یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اسلام غالب آئے گا بلکہ اس کا غلبہ دائمی ہوگا اگر کسی وقت کسی دشمن نے اسلام پر حملہ کرکے اس کو مٹانے کی کوشش کی توا للہ تعالیٰ اپنی زبردست طاقت سے ایسے دشمن کو تباہ کر دے گا اور اسلام کی کمزوری کو دور کرکے پھر اس کو غالب کردے گااور اگر اسلام کے اندرکسی وقت ضعف پیدا ہوا تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ہو گا اور اس کے بعد پھر سے اسلام کا سورج ساری دنیا کو منوّر کرنے لگ جائے گا.اس سورۃ کا تعلق سورۂ کوثر سے بھی ہے.سورۂ کوثر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو وعدے کئے گئے تھے.(۱)کثرت جماعت کا وعدہ.(۲) دشمنوں کی تباہی کا وعدہ.گویا پہلے وعدہ کے پورا ہونے کا ذکر سورۃ نصر میں کیا گیا ہے اور دوسرے وعدے کے پورا ہونے کا ذکر سورۂ لہب میں ہے.اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو بالکل ابتدائی زمانہ میں نازل فرما کر مسلمانوں کی ہمت بندھائی کہ گھبرائو نہیں گو تم کمزور اور ضعیف ہو.لیکن تمہارا مددگار وہ طاقت ور خدا ہے کہ جس کے منشاء کے ماتحت زمین و آسمان کے ذرّات حرکت میں آتے ہیں.پس جو بھی تمہاری مخالفت کرے گا وہ رسوا و خوار ہو گا اور تباہی کا منہ دیکھے گا.پھر مضمون کے اعتبار سے اس سورۃ کو بالکل آخر میں رکھا تا آئندہ آنے والی نسلوں کے حوصلے بلند ہوں اور کسی زمانہ میں کفر کی طاقت کو دیکھ کر مسلمان گھبرا نہ جائیں.بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اسلام کا خدا غالب خدا ہے اور وہ اس کے دشمنوں کو خود تباہ کر دے گا.گویا سورۃ نصر اور سورۃ لہب اُمت کے نام دو آخری پیغام ہیں.ایک زیادتیٔ ایمان اور ترقیٔ ایمان کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا کفر کی ہلاکت کی طرف ذہن کو منتقل کرتا ہے.
Page 352
سورۃ لہب کا سبب نزول اس سورۃ کے سبب نزول کے متعلق مختلف روایات تفاسیر میں بیان ہوئی ہیں.سب سے پہلی روایت یہ آتی ہے:.قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ کَانَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَکْتُمُ اَمْرَہٗ فِیْ اَوَّلِ الْمَبْعَثِ وَیُصَلِّی فِیْ شِعَابِ مَکَّۃَ ثَلَاثَ سِنِیْنَ اِلیٰ اَنْ نَزَلَ قَوْلُہٗ تَعَالیٰ وَاَنْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ فَصَعِدَالصَّفَا وَنَادٰی یَااٰلَ غَالِبٍ فَــخَـرَجَتْ اِلَیہِ غَــالِــبٌ مِّـنَ الْـمَـــسْـــجِـــدِ فَــقَــالَ اَ بُـــوْلَھَبٍ ھٰــذِہِ غَــالِبٌ قَدْ اَتَـتْـکَ فَـمَــا عِــنْـدَکَ ثُمَّ نَـادٰی یَا اٰلَ لُــؤَیٍّ فَــرَجَــعَ مَــنْ لَّــمْ یَــکُــنْ مِّــنْ لُــؤَیٍّ فَقَالَ اَ بُــوْ لَــھَــبٍ ھٰــذِہٖ لُـــؤَیٌّ قَــدْ اَتَتْکَ فَـمَا عِنْدَکَ ثُمَّ قَالَ یَا اٰلَ مُـــرَّۃَ فَـــرَجَـــعَ مَــنْ لَّــمْ یَــکُــنْ مِّــنْ مُّــرَّۃَ فَــقَــالَ اَ بُــوْلَــھَــبٍ ھٰــذِہٖ مُــرَّۃُ قَـدْ اَتَتْکَ فَـمَا عِنْدَکَ ثُمَّ قَالَ یَا اٰلَ کِلَابٍ ثُمّ قَالَ بَعْدَہٗ یَا اٰلَ قُصَیٍّ فَقَالَ اَبُوْ لَھَبٍ ھٰذِہٖ قُصَیٌّ قَد اَتَتْکَ فَـمَا عِنْدَکَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰہَ اَمَرَنِی اَنْ اُنْذِرَعَشِیْرَتِیَ الْاَقْرَبِیْنَ وَ اَنْتُمُ الْاَقْرَبُوْنَ.اِعْلَمُوْا اَنِّی لَا اَمْلِکُ لَکُمْ مِّنَ الدُّنْیَا حَظًّا وَّلَا مِنَ الْاٰخِرَۃِ نَصِیْبًا اِلَّا اَنْ تَقُوْلُوْا لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ فَاَشْھَدُ بِـھَا لَکُمْ عِنْدَ رَبِّکُمْ فَقَالَ اَبُوْلَھَبٍ عِنْدَ ذٰلِکَ تَبًّا لَکَ اَلِھٰذَا دَعَوْتَنَا فَنَزَلَتِ السُّوْرَۃُ.( التفسیر الکبیر للامام رازی سورۃ المسد) یعنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بعثت کے ابتدائی زمانہ میں یعنی تین سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ زور سے تبلیغ نہیں فرماتے تھے اور مکّہ کی مختلف گھاٹیوں میں نماز اداکر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی.وَاَنْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کرو.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ صفا پر چڑھ گئے اور مختلف قبائل کو بلانا شروع کیا.سب سے پہلے آل غالب کو بلایا اور وہ مسجد حرام سے نکل کر آگئے.ابو لہب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آل غالب تو آگئے ہیں اب مقصود بیان کریں.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی بات پر توجہ نہ دی اور لویّ قبیلہ کے افراد کو پکارا.اس پر وہ بھی پہنچ گئے پھر ابولہب نے کہا کہ اب تو لؤیّ قبیلہ بھی آگیا.اب آپ بتائیں کہ کیاکہنا چاہتے ہیں.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی اور آل مُرّہ کو پکارا.چنانچہ وہ بھی پہنچ گئے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل کلاب اور آل قصیّ کو بلایا.جب سب آگئے تو آپ نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اقرباء کو آنے والے عذاب سے خبردار کروں.سوتم میرے اقرباء ہو اور تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں تمہارے لئے دنیا اور آخرت سے کسی چیز کا ضامن نہیں ہو سکتا.سوائے اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو.اور لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کہو.اس پر ابولہب غصہ میں آگیا اور اس نے بڑے جوش
Page 353
سے کہا تَبًّا لَکَ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم ہلاکت کامنہ دیکھو.کیا تم نے اسی غرض کے لئے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کے اس قول کے مطابق یہ سورۃ نازل ہوئی.اور یہ بتایا گیا کہ تباہی ابو لہب کے لئے ہوگی نہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے.دوسری روایت سبب نزول کے متعلق یہ بیان ہوئی ہے.عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَت وَاَنْذِرْ عَشِیْـرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ صَعِدَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَلَی الصَّفَا فَـجَعَلَ یُنَادِیْ یَا بَنِیْ فِھْرٍ یَا بَنِیْ عَدِیٍّ لِبُطُوْنِ قُرَیْشٍ حَتّٰی اِجْتَمَعُوْا فَـجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ اَنْ یَّـخْرُجَ اَرْسَلَ رَسُوْلًا لِیَنْظُرَ مَاھُوَ فَـجَآءَ اَبُوْ لَھَبٍ وَقُرَیْشٌ فَقَالَ اَرَاَیْتَکُمْ لَوْ اَخْبَرْتُکُمْ اَنَّ خَیْلًا بِالْوَادِیْ تُرِیْدُ اَنْ تُغِیْرَ عَلَیْکُمْ اَکُنْتُمْ مُصَدِّقِیَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَیْکَ اِلَّا صِدْقاًقَالَ فَاِنِّی نَذِیْرٌ لَّکُمْ بَیْنَ یَدَیْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ.فَقَالَ اَبُوْلَھَبٍ تَبًّا لَکَ سَائِرَا لْاَیَّامِ اَلِھٰذَا جَـمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ وَیُرْوٰی اَنَّہٗ مَعَ ذٰلِکَ الْقَوْلِ اَخَذَ بِیَدَیْہِ حَـجَرًا لِیَـرْمِیَ بِـھَا رَسُوْ لَ اللّٰہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ.( روح المعانی سورۃ اللھب) یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وَاَنْذِرْ عَشِیْرَتَکَ الْاَقْرَبِیْنَ کی آیت نازل ہوئی.تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور عرب کے مختلف قبائل کو پکارنے لگے.یہاں تک کہ لوگ کوہ صفا پر پہنچ گئے اور جو خود نہ آسکا اس نے اپنا ایلچی بھیج دیا تاکہ معلوم کر کے اطلاع دے کہ کس غرض کے لئے بلایا گیا ہے.چنانچہ اس موقعہ پر قبیلہ قریش اور ابو لہب بھی پہنچ گیا.تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پَرے وادی میں ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر شب خون مارنا چاہتا ہے.تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں.ہمارا یہ تجربہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولاکرتے ہیں.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.لو سنو ! میں تمہیں ایک اہم خبر سناتاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں.اس پر ابو لہب بھڑک اٹھا اور اس نے کہا تَبّاً لَکَ.اے محمد (نعوذباللہ) تم پر ہلاکت ہو.کیا تم نے اس معمولی سی بات کے لئے ہم کو جمع کیا تھا؟ چنانچہ اس کے جواب میں یہ سورۃ نازل ہوئی.بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو لہب نے ایک پتھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکنا چاہا.اس لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے.غرض یہ دو روایات سورۃ لہب کے سبب نزول کے متعلق بیان کی جاتی ہیں.لیکن اس بارہ میںیہ بات یاد رکھنی چاہیے
Page 354
کہ آیات کے سبب نزول کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی مروی نہیں.صرف صحابہ کرام کی بیان کردہ روایات ہوتی ہیں تبھی بعض اوقات ان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے.اور ایک آیت کے متعلق کئی کئی سبب نزول بیان ہو جاتے ہیں.اس سورۃ کے متعلق بھی جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے وہ حضرت ابن عباسؓ کی طرف منسوب ہے اور تفاسیر میں اس سورۃ کے متعلق ان کے سوا کسی اور کی طرف سے بیان کردہ روایت نہیں پائی جاتی.حالانکہ یہ سورۃ ابتدائی زمانہ کی ہے اور اس زمانہ کے صحابہ میں سے حضرت ابن مسعودؓ اور حضرت علیؓ بڑے پایہ کے ہیں.لیکن انہوں نے کوئی روایت نہیں کی.حضرت ابن عباسؓ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب کہ یہ سورۃ نازل ہوئی.انہوں نے مدینہ میں جا کر ہوش سنبھالی ہے.اور ان کا علم مکی سورتوں کے متعلق صرف سماعی ہے.پس ان حالات میں ہم یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس سورۃ کے متعلق بیان کردہ شان نزول قطعی اور یقینی ہے.بےشک قرآن کریم کی ہر سورۃ کے پہلے مصداق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانہ کے لوگ ہی ہیں لیکن جیساکہ پہلی سورتوں میں بتایا جا چکا ہے آخری چند سورتوں کی ترتیب یہ ہے کہ ایک سورۃ زیادہ تر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی طرف توجہ دلاتی ہے اور ایک زیادہ تر آخری زمانہ کی طرف.ہماری ترتیب کے مطابق سورۃ لہب اس مقام پر ہے جو زیادہ تر آخری زمانہ کی طرف توجہ دلاتی ہے کیونکہ سورۃ لہب سے پہلی سورۃ یعنی سورۂ نصر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے.مفسرین کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام عبدالعزیٰ تھا جس کی کنیت ابولہب پڑ گئی تھی.کیونکہ اس کا رنگ بہت سرخ و سفید تھا (البحر المحیط سورۃ اللہب).قرآن شریف نے سورۃ لہب میں اس کی مخالفتوں کا ذکر کیا ہے.لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مخالفت کے لحاظ سے ابو جہل جس کا نام ابوالحکم تھا عبدالعزیٰ سے بہت بڑھا ہواتھا.اور سارے قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مخصوص دشمن یا منافق کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا.بلکہ اگر کسی دشمن کا ذکر آیا ہے تو اشارہ کے ساتھ آیا ہے جو عام الفاظ میں ہے اور مختلف انسانوں پر چسپاں ہوسکتا ہے.مثلاً آدمؑ کے دشمن کو دو صفاتی ناموں سے یاد کیا گیا ہے.ایک شیطان اور ایک ابلیس (دیکھو سورۂ بقر ہ ع ۴ و اعراف ع۲ و طٰہٰ ع۷) یعنی وہ حق سے دور تھا اورخدا کی رحمت سے مایوس تھا.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شدید مخالف کوجو آپ کے خلاف لوگوں کو لڑائی کے لیے اکساتاتھا شیطان کے لفظ سے یاد کیا ہے.لیکن اس کا اصل نام نہیں لیا.( سورۃ الانفال ع ۶ آیت ۴۸) اس سورۃ میں بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن سے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ ہو.بلکہ کئی لوگوں پر یہ مضمون چسپاں ہو سکتا ہے.
Page 355
اس طریق کلام کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ عبدالعزیٰ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا وہ مخالفت میں کئی اور دشمنوں سے ادنیٰ تھا.ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورۃ میں جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے بعض ایسے دشمنوں کا ذکر کیا گیا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی پر لوگوں کو اکساتے تھے.اور مفسروں کا یہ کہنا کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے چچا کا ذکر ہے جس کا چہرہ سرخ و سفید تھا درست معلو م نہیں ہوتا.ابولہب کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ شخص آگ بھڑکاتا تھا.اور آیت وَّ امْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ بھی بتاتی ہے کہ یہاں آگ بھڑکانے کا ذکر ہے، چہرہ کی سفیدی کا ذکر نہیں.اگر چہرہ کی سفیدی کی وجہ سے کسی کو ابو لہب کہا گیا ہے.تو اس کی بیوی کے لکڑیا ں اٹھا کر لانے اور آگ میں جھونکنے کا کیا مطلب ہے.کیا اس کی لکڑیوں سے ابو لہب کے چہرہ کی سفیدی بڑھا کرتی تھی؟ پس حقیقت یہ ہے کہ اس سورۃ میں ان شدید دشمنوں کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ کی آگ بھڑکاتے رہتے تھے.اور بتایا ہے کہ وہ ناکام رہیں گے.لیکن سورتوں کی ترتیب کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے ( جو تفسیر میں سب سے اہم مقام رکھتی ہے ) اس سورۃ میں آخری زمانہ کا ذکرہے.اورایک ایسی قوم کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف سخت آگ بھڑکائے گی.اور بتایا گیا ہے کہ وہ جماعت کوشش کرکے اپنی ہمسایہ قوموں کواپنے ساتھ ملائے گی اور وہ اس کے ہاتھ کی مانند ہوںگے یعنی اس کے مددگار ہوں گے.ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں دوہی جتھے ایسے ہیں جو کہ اسلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد ہیں.ایک جتھہ بعض مغربی طاقتوں پر مشتمل ہے اورایک جتھہ مشرقی طاقتوں اور ان کے ساتھیوں کا ہے.ابو لہب سے مراد یہ دونوں جتھے ہیں.جو ظاہر میں بھی ابو لہب ہیں کیونکہ ان کے رنگ سرخ و سفید ہیں اور باطنی لحاظ سے بھی ابو لہب ہیں کیونکہ آگ کی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تیار کر رہے ہیں اور اس لحاظ سے بھی وہ ابو لہب ہیں کہ ان میں سے بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لٹریچر پیدا کرتے رہتے ہیں اور اسلامی حکومتوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہتے ہیں.اور ایک جتھہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف کوشش کر رہا ہے اور دہریت پھیلا رہا ہے.یعنی مشرقی جتھہ جس نے بہت بڑی اسلامی حکومتوں کو تہ و بالا کر دیا ہے مثلاً سمر قند، بخارا اور سنکیانگ کے علاقے اس نے اپنے قبضہ میں کر لئے ہیں.اور ٹرکی اور عراق اور ایران کے خلاف وہ منصوبے کرتا رہتا ہے.پس یہ دونوں طاقتیں اس وقت اپنی ظاہری تدبیروں اور مذہبی مخالفتوں کی وجہ سے ابو لہب کہلانے کی مستحق ہیں.اس سورۃ میںیہ بتایا گیا ہے کہ ابولہب کے نام کی مستحق اقوام جو آخری زمانہ میں پیدا ہوں گی.اللہ تعالیٰ ان کو
Page 356
اوراُن کے ساتھیوںکو نا کام کردے گا.یہ ایک سیاسی سوال ہے جس میںہم پڑنا نہیں چاہتے کہ اس وقت مشرقی طاقت کے کون سے دو مویّد ہیں.جو اس کی جنگی کارروائیوں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور مغربی جمہوریت کے کون سے دو مویّد ہیں جو اس کی جنگی طاقتوں میں اس کی مدد کررہے ہیں.بہر حال یہ ظاہر ہے کہ ایک طرف مغربی جمہوریت اپنے ساتھی بڑھا رہی ہے اور ایک طرف اس کے مقابل کی مشرقی طاقت اپنے ساتھی بڑھا رہی ہے اور دونوں جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہیں.یہ سورۃ بتاتی ہے کہ یہ اتحاد کام نہ دیں گے اور جن ہاتھوں پر امیدیں کی جارہی ہیں.انہی ہاتھوں کو خدا شل کردے گا.اس کے بعد فرماتا ہے کہ علاوہ غیرقوموں کے جو کہ بطور ہاتھ کے ہیں.خود ان ملکوں میں بھی ایسے گروہ پائے جائیں گے جو کہ خدا تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اپنی حکومتوں کو بھڑکائیں گے.صاف ظاہر ہے کہ ایسے گروہ مغربی ممالک میں بھی موجود ہیں اور مشرقی ممالک میں بھی موجود ہیں.ان گروہوں کانام اس مناسبت سے کہ وہ اندرونی ہیں.اِمْرَاَۃٌ رکھا گیا ہے یعنی بیوی.اور فرماتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی بھی تباہ ہو جائے گی یعنی ان قوموں کے وہ گروہ بھی کمزور ہو جائیں گے اور نقصان اٹھائیں گے جو لکڑیاں ڈال ڈال کر حکومت کی آگ کی طاقت کو بڑھا رہے ہیں.لکڑیاں ڈالنے سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ وہ حکومت کو شہ دلاتے ہیں کہ تم ایسے کام کرو.جیسا کہ مغربی ممالک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اسلام کے خلاف لٹریچر لکھواتے ہیں اور اسرائیل کی تائید کے لئے ان ممالک کو اکساتے رہتے ہیں.اسی طرح مشرق میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی قوم کو اور اپنی حکومت کو دہریت کی تائید میں اکساتے رہتے ہیں اور توحید کے خلاف جنگ پر آمادہ کرتے رہتے ہیں.اس سورۃ سے پتہ لگتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ ان دونوں فتنوں کو دور کردے گا.نہ مغربی جمہوریت کے اشتعال پسند لوگ محفوظ رہیں گے نہ اس کے مقابل کی مشرقی طاقت کے اشتعال پسند لوگ محفوظ رہیں گے.پھر فرماتا ہے کہ باوجود بچنے کی ساری تدبیروں کے ان کو کسی جنگ میں مبتلا ہونا پڑے گا جو بڑی شعلوں والی ہوگی.اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شائد کسی وقت ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی جنگ ہو جائے گی.لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسا کہ قرآن شریف کی آیات سے پتہ لگتاہے، عذاب ٹل بھی جایا کرتے ہیں.اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور سچی توبہ اور استغفار سے کام لیں تو یہ عذاب ٹل بھی سکتا ہے.ضروری نہیں کہ اسی شکل میں آئے.ممکن ہے کہ ایٹم بم کی جگہ اصولوں کی مخالفت اور مقابلہ کی صورت میں ہی یہ پیشگوئی پوری ہو جائے.
Page 357
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ ( میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا ( اور ) بار بار حم کرنے والا ہے( شروع کرتاہوں) تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّؕ۰۰۲ شعلہ کے باپ کے دونوں ہاتھ ہی شل ہو گئے ہیں اور وہ (خود ) بھی شل ہو کر رہ گیا ہے.حلّ لُغات.تَبَّتْ.تَبَّتْ تَبَّ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور تَبَّ یَتُبُّ تَبًّا کے معنے ہیں ھَلَکَ وَخَسِـرَ.تباہ و برباد ہو گیا اور اس نے نقصان اٹھایا.اور جب تَبَّتْ یَدَاہُ کا فقرہ بولیں تو اس کے معنی ہوں گے ضَلَّتَا وَخَسِـرَتَا.اس کے دونوں ہاتھوں نے نقصان اٹھایا اور تباہ ہوئے.(اقرب) مفردات امام راغب میں لکھا ہے اَلتَّبُّ وَالتَّبَابُ اَلْاِسْتِمرَارُ فِی الْـخُسْـرَانِ.یعنی اَلتَّبُّ وَالتَّبَّابُ (جو تَبَّ فعل کے مصدر ہیں ) کے معنے ہیں ہمیشہ گھاٹا اٹھانا.اور تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ کے معنے ہیں اِسْتَمَرَّتْ فِیْ خُسْـرَانِہٖ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ضرور نقصان اٹھائیں گے.اَلْیَدُ.اَلْیَدُ کے معنے ہیں اَلْکَفُّ ہاتھ.نیز اس کے معنے ہیں اَلْـجَاہُ وَالْوَقَارُ.عزت و رتبہ.اَلْقُوَّۃُ وَالقُدْرَۃُ وَالسُّلْطٰنُ وَالْوِلَایَۃُ.قوت و طاقت.بادشاہت اور غلبہ.اَلْـجَمَاعَۃُ.جماعت.اَلنِّعْمَۃُ وَالْاِحْسَانُ احسان اورنعمت.(اقرب) اَلْاَبُ.اَلْاَبُ: اَلَّذِیْ یَتَوَلَّدُ مِنْہُ اٰخَرُ مِنْ نَوْعِہٖ.یعنی اس وجود کو جس سے اسی نوع کی چیز پیدا ہو جس نوع کا وہ خود ہے.اَبٌ کہتے ہیں یعنی والد.نیز اَبٌ کے معنے ہیں مَنْ کَانَ سَبَبًا فِیْ اِیْـجَادِ شَيْءٍ اَوْاِصْلَاحِہٖ اَوْ ظُھُوْرِہٖ جو کوئی کسی چیز کے ایجاد کرنے یا ظاہر کرنے اور وجود میں لانے کا سبب ہو اس کو بھی اَبٌ کہتے ہیں.(اقرب) لَھَبٌ.لَھَبٌ لَھِبَ کا مصدر بھی ہے اور اسم بھی ہے.لَھِبَتِ النَّارُ کے معنے ہوتے ہیں اِشْتَعَلَتْ خَالِصَۃً مِّنَ الدُّخَانِ.آگ ایسی تیزی سے بھڑک اٹھی کہ اس میںدھواں باقی نہ رہا.اور اَللَّھَبُ کے معنے ہوتے ہیں.لِسَانُ النَّارِ یعنی آگ کا شعلہ.(اقرب) پس ابو لہب کے معنے ہوں گے شعلوں کا باپ.یعنی ایسی چیزوں کاموجد جو آگ کو بھڑکائیں.تفسیر.آنحضرت صلعم کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
Page 358
صداقت اور آپ کے منجانب اللہ ہونے کے دلائل میں سے ایک زبردست دلیل یہ ہے کہ جب آپ نے دعویٰ کیا اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق اعلان کیا کہ آپ جس مقصد کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں اس میں آپ بہرحال کامیاب ہوں گے.گودنیا آپ کی مخالفت کرے گی لیکن کوئی شخص آپ کا بال تک بیکانہیں کرسکے گا.آپ وہ کونے کا پتھر ہیں کہ جس پر آ پ گرے وہ بھی چکنا چو رہوگااور جو آپ پر گرے گا وہ بھی چکنا چور ہوجائے گا.تاریخ شاہد ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ درست نکلا.دعویٰ کے بعد مخالفت کے بڑے بڑے طوفان آئے لوگوں نے آپ کے قتل کے منصوبے کئے.آپ کے متبعین کو ختم کرنے کی تدبیریں کی گئیں.ایسے حالات میں جبکہ کامیابی کی کوئی امید نہیں ہوسکتی تھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باربار یہی اعلان فرماتے کہ آپ کامیاب ہوںگے.اسلام مغرب و مشرق میں پھیل جائے گا.ساری دنیا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوگی اور پھر یہی نہیں کہ اسلام کی زبردست حکومت قائم ہوجائے گی بلکہ آخر اس پر ایک ایسا وقت آئے گا جب اسلام کے ماننے والے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑدیں گے.ان پر تنزّل وادبار آجائے گا ان کی حکومتیں ختم ہوجائیں گی اور بعض نئی برسراقتدار آنے والی قومیں اسلامی ممالک کو دبالیں گی اور اسلام بے سروسامانی کی حالت میں ہو جائے گا.تب اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گا اور پھر سے اسلام زندہ ہوگا.اور اس کے دشمن ختم ہوں گے.اور اسلام کادوبارہ احیاء ہوگا.یہ وہ خبریں ہیں جو قرآن کریم میں ہمیں کثرت سے ملتی ہیں اور ایسی خبریں اور ان کی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہؓ کے سامنے بیان فرمائیں جن میں سے بعض احادیث کی کتب میں محفوظ ہو کر ہم تک پہنچ گئی ہیں.اور یہ سب باتیں لفظاً لفظاً پوری بھی ہو گئیں.پس ایسے وقت میںجبکہ بظاہر کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے تھے.اپنی ترقی اور اپنے عروج کی خبریں دینا اور عروج کے بعد پھر قوم کے تنزّل کی پیشگوئی کرنا اور پھر کہنا کہ اس تنزل کے بعد پھر عروج ہوگا یہ سب کچھ محض دماغ کے تصوّرات نہیں ہو سکتے.بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے ہی یہ سب خبریں دی تھیں تبھی تو غیر معمولی حالات میںپوری ہوئیں.پس ان سب خبروں کا پورا ہونامحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت ہے اور یہ بتاتا ہے کہ آپ منجانب اللہ تھے.آج یوروپین ممالک بام عروج پر پہنچے ہوئے ہیں.ان کی تہذیب، ان کا تمدن اور ان کی ایجادات کو دیکھ کر سب دنیا دنگ ہے اور یہ لوگ خود بھی ان سب باتوں کواپنی فوقیت میں پیش کرتے ہیں.آج ہر ملک کی نگاہ ان کی طرف اٹھتی ہے اور ہر قسم کے علوم کا منبع ان کے ممالک کو سمجھا جاتا ہے.مسلمانوں کی وہ حکومتیں جن سے دنیا کانپ اٹھتی تھی جن کے سامنے یوروپین ملکوں کے لوگ شاگردوں کی طرح بیٹھتے تھے.جن کے گھوڑوں نے ان کے ملکوں کو
Page 359
روند ڈالا.آج سمٹ سمٹا کر محدود علاقوں میں رہ گئی ہیں.وہ شیر جس کے سامنے سب ممالک چوہوں کی طرح تھے.آج وہ شیر اتنا کمزور اور ضعیف ہے کہ یہ چوہے اس کے جسم پر دوڑتے پھر رہے ہیں اور اس کو نوچتے ہیں اور شیر میں اتنی قوت نہیں کہ ان چوہوں کو بدن سے ہٹا سکے.آج کا مسلمان بھی مایوس ہو چکا ہے اور سمجھتا ہے کہ اسلام آج ہے تو کل نہیں.اور جو کوئی یوروپین ممالک میں جاتا ہے اور وہاں کی ترقی اور عروج کوبنظرِخود مشاہدہ کرتا ہے وہ مجسم یاس اور ناامیدی بن جاتا ہے اور واپس پہنچ کر یہی پیغام دیتا ہے کہ اسلام کا اب خدا ہی حافظ ہے.بظاہر اس کے دوبارہ ترقی کرنے کا امکان نہیں.کیونکہ ایک طرف اس کے دشمنوں نے اس کی سیاسی طاقت کو ختم کردیا ہے اور دوسری طرف اسلام کے ماننے والوںنے خود اسلام کو خیرباد کہہ دیا اوریورپ کو اپنا امام سمجھ کر اس کی اقتدا کو فخر خیال کرنے لگ گئے اورانہوں نے یہ بھلا دیا کہ ایک مسلمان کو جو کتاب بطور مکمل ضابطہ حیات کے دی گئی ہے.وہ اس لئے نہیں کہ یہ دوسروں سے راہنمائی حاصل کرے بلکہ اس لئے ہے تالوگ اس کے نور سے منور ہوں اور اس کی پیروی سے دین و دنیا میں فائدہ اٹھائیں.اسلام کے عروج و زوال کی پیشگوئیاں درحقیقت اسلام کا تنزل اور یوروپین ممالک کا یہ عروج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے.کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب خبریں آج سے تیرہ سو سال پہلے بتا دی تھیںاور اتنی تفصیل سے بتائیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے.یوں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سینما کی فلم دکھائی جاتی ہے.اسی طرح آپ کو وہ تمام حالات پردہ پر دکھادیئے گئے جن سے اسلام دوچار ہونے والا تھا اور ان سب واقعات کے رونما ہونے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر مہر لگادی.کیونکہ اتنا علم غیب جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کبھی کسی شخص کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوسکتا جب تک کہ خدائے عالم الغیب اس کو نہ بتائے.پس اسلام کا یہ ضعف، یہ بے کسی اس واسطے نہیں کہ ہم گھبرا جائیں، ہم مایوس ہوجائیں بلکہ جس خدا نے اسلام کے تنزل کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ نے اپنے صحابہ کو بتائی اور وہ لفظ بلفظ پوری بھی ہوئی.اسی خدا کی طرف سے آپ کو ایک اور خبر بھی دی گئی اور وہ یہ کہ اسلام دوبارہ ترقی کرے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا اس سے ٹکرانے والے پاش پاش ہوں گے.اور اسلام کا جھنڈا ساری دنیا پر لہرائے گا.لیکن یہ سب کچھ خدا تعالیٰ خود کرے گا.جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہواتھا اسی طرح آخری زمانہ میں دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح دنیامیں آئے گی اور خدا کی نصرت اور اس کے فضل کو جذب کرے گی اور ملائکہ کی فوجیں آسمان سے اتر کر کمزوروں کو طاقتور اور سلطنتوں کا وارث بنادیں گی.پس کسی مسلمان
Page 360
کے لئے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں.اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے.اور انتہائی کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ مناسب اسباب اور ذرائع کے اختیار کرنے سے جلد سے جلد وہ مقصد حاصل ہوجائے اور پورے وثوق کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے.ذیل میں ہم بعض ان اخبار کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کریم اور حدیث میں موجودہ زمانہ کے متعلق بیان کی گئی ہیں.اور ان کاتعلق سورۂ لہب کے مضمون کے ساتھ ہے.تاایک مسلمان کے لئے ان کو پڑھ کر زیادتیٔ ایمان کا موجب ہو کہ کس طرح آج سے تیرہ سو سال قبل بیان کی ہوئی خبریں پوری ہورہی ہیں اور وہ یہ یقین کر لے کہ دوسری خبریں جو اسلام کی ترقی کے متعلق ہیں وہ بھی اسی طرح پوری ہوں گی جس طرح سے یہ خبریںپوری ہوئی ہیں.سو جاننا چاہیے کہ آخری زمانہ میں اسلام نے جن مصائب اور فتنوں سے دوچار ہونا تھا ان فتنوں میں سے دووجودوں کا خاص طور پر ذکر آتا ہے.اور ان وجودوں کے فتنوں کا خاص طور پر ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ ان سے اسلام کو خاص طور پر نقصان پہنچنا تھا.ایک وجود کا نام دجّال رکھا گیا ہے اور دوسرے فتنہ کے دوظہور بیان کئے گئے ہیں.ایک ظہور کا نام یاجوج اور ایک کانام ماجوج بتایا گیا ہے.چنانچہ مسلم کی حدیث میں ہے :.خروج دجال اور یاجوج وماجوج کے متعلق پیشگوئی عَنْ حُذَیْفَۃَ ابْنِ اُسَیْدٍ الْغَفَّارِیِّ قَالَ اِطَّلَعَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَلَیْنَا وَنَـحْنُ نَتَذَاکَرُ فَقَالَ مَا تَذْکُرُوْنَ قَالُوْا نَـذْکُرُ السَّاعَـــۃَ قَــالَ اِنَّـھَا لَنْ تَــقُــوْمَ حَـتیّٰ تَـرَوْا قَـبْـلَـھَا عَـشْــرَ اٰیَاتٍ.فَـذَکَـرَ الـدُّخَانَ وَ الـدَّجَّالَ والدَّٓآ بَّۃَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِـھَا وَنُزُوْلَ عِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَیَاجُوْجَ وَمَاجُوْجَ وَثَلٰثَۃُ خَسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْـرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِـجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَـخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَـحْشَـرِهِمْ.( مسلم بـحوالہ مشکوٰۃ کتاب الفتن الفصل الاول باب العلامات بین یدی الساعۃ ) یعنی حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ایک دن ہم چند لوگ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھانکا اور دریافت فرمایا کہ کیا باتیں کررہے ہو.ہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کررہے ہیں.آپ نے فرمایا کہ اس کے برپا ہونے سے قبل دس علامات کا ظاہر ہونا ضروری ہے اور آپ نے حسب ذیل علامات گنوائیں.دخان، خروج دجال، خروج دابہ، طلوع الشمس من المغرب، نزول عیسیٰ بن مریم، خروج یاجوج و ماجوج اور
Page 361
تین ایسے واقعات جن سے لوگ زمین میں دھنسیں گے.ایک ایسا واقعہ مشرق میں ہوگا اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں اور آخری علامت یہ بتائی کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی.ان علامات میں دجّال اور یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے او رغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت یہ دونوں فتنے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور ایک ہی فتنہ کی مختلف شاخیں ہیں.یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں یاجوج و ماجوج کا تو ذکر آتا ہے لیکن دجال کا ذکرنہیں آتا.حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت زیادہ بیان فرمائی ہے.چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :.ذَکَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ اِنِّیْ لَاُنْذِرُکُمُوْہُ وَمَامِنْ نَّبِیٍّ اِلَّا اَنْذَرَقَوْمَہٗ لَقَدْ ااَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَہٗ.(کنزالعمال جلد ۷ ص ۱۹۵ بحوالہ ابو داؤد و ترمذی ) یعنی دجال کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس نے اپنی امت کو دجال سے ہوشیار نہ کیا ہو.نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ہوشیار کیا اور میں بھی اس کی خبر دیتا ہوں اور قوم کو ہوشیار رہنے کی تلقین کرتاہوں.پس اتنے بڑے فتنے کا ذکر قرآن کریم میں نہ آنا اور یاجوج ماجوج کا ذکر آنا بتاتا ہے کہ در حقیقت یاجوج و ماجوج اور دجّال کا فتنہ ایک ہی چیز کے دونام ہیں یاایک ہی فتنہ کی دوشاخیں ہیں.اس کی مزید تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ دجّال اور یاجوج وماجوج کا ایک ہی زمانہ ہے.اور پھر یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ دونوں ساری دنیا پر غالب آجائیں گے یہ باتیں بتاتی ہیں کہ یہ دجّال اور یاجوج و ماجوج کے فتنے کوئی الگ قسم کے فتنے یا الگ زمانوں کے فتنے نہیںہیں.بلکہ ایک ہی فتنہ کے مختلف مظاہر ہیں.درحقیقت دجال مذہبی پہلو سے اس فتنہ کا نام رکھا گیا ہے.دجّال کے معنے ہوتے ہیں ملمّع ساز، فریب کرنے والا.پس آخری زمانہ کا فتنہ جس سے کہ بنو اسرائیل کے انبیاء بھی ڈراتے رہے ہیں اس کے دو حصے ہونے تھے.ایک حصہ تو مذہبی عقائد اور مذہبی خیالات میں فساد پیدا کرنے کے متعلق تھااور ایک حصہ سیاسی حالات اور سیاسی امن کو برباد کرنے کے متعلق تھا.جو مذہبی عقائد سے متعلق فتنہ تھا اس کے بھڑکانے والی روح کو دجّال کہا گیا ہے یعنی فریب اور دھوکا دینے والی ہستی.اور جو فتنہ کہ سیاسی پہلوئوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا اس کے بھڑکانے والی ہستیوں کو یاجوج اور ماجوج کہا گیا ہے.یاجوج ماجوج کے الفاظ اجیج سے نکلے ہیں اور اَجَّتِ النَّارُ اَجِیْجًا کے معنے ہیں تَلَھَّبَتْ.آگ بھڑک اٹھی اور جب اجَّـجْتَ النَّارَ کہیں تو معنے ہوں گے اَلْھَبَتْـھَا فَالْتَـھَبَتْ کہ آگ کو بھڑکا! تو وہ بھڑک اٹھی.( اقرب) پس لفظ اَجَّ کے معنے آگ بھڑکانے کے
Page 362
ہیں اور یاجوج و ماجوج کے الفاظ ایسی ہستیوں پر دلالت کرتے ہیں جو ایسی طاقت رکھیں گے کہ آتشین اسلحہ کے استعمال سے دنیا پر غلبہ پالیں گے.اس تشریح کے بعد ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی ان خبروں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ یاجوج و ماجوج کے متعلق آتی ہیں.خروج یاجوج و ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَ مَاْجُوْجُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ(الانبیآء:۹۷) کہ ایک زمانہ تک یاجوج و ماجوج کو دنیا کے کناروں پر بند رکھا جائے گا.اس کے بعد وہ دیوار جو ان کو روکے ہوئے ہو گی، ٹوٹ جائے گی.یعنی اسلام کی حکومت جاتی رہے گی اور اس کا زور ٹوٹ جائے گا.اس کی روحانی طاقت بھی کمزور پڑجائے گی اور مسلمان اپنے دین کو بھول جائیں گے.چنانچہ اس زمانہ کی تعیین کے متعلق سورۂ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :.يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.(السجدۃ:۶) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام ترقی کرے گا اورپھر جیسا کہ حدیثوں میں ہے.تین سو سالوں کے بعد وہ کمزور ہونا شروع ہوگااور ایک ہزار سال تک برابر کمزور ہوتا جائے گا.گویا یہ زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سو سال بعد کا ہے.پھرآیت حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَ مَاْجُوْجُ وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج سمندر پار رہنے والی اور پہاڑوں کے پَرے رہنے والی قومیں ہیں.چنانچہ آیت کے الفاظ یہ ہیں وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ اور حَدَبْ کے معنے لغت میں موج اور اونچی اور سخت زمین کے لکھے ہیں(اقرب).پس مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج جو سمندر پار رہنے والی اور پہاڑوں کے پَرے رہنے والی اقوام ہیں.وقت موعود پر پہاڑوں سے اور سمندروں کی موجوں پر سوار ہوکر ایشیا میں اتر پڑیں گی.ایشیا کا نام ہم اس لئے لیتے ہیں کہ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دشمنوں کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایشیا میں ہی بستی ہے.اسی طرح سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :.حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا١ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا.قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا.قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ۠ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا.اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ١ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا١ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا١ۙ قَالَ اٰتُوْنِيْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا.فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ
Page 363
نَقْبًا.قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ١ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ١ۚ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا.وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا.وَّ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَىِٕذٍ لِّلْكٰفِرِيْنَ عَرْضَا.ا۟لَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِيْ غِطَآءٍ عَنْ ذِكْرِيْ وَ كَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ۠ سَمْعًا.اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِيْ مِنْ دُوْنِيْۤ اَوْلِيَآءَ١ؕ اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ نُزُلًا.قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا.اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.(الکہف:۹۴تا۱۰۵) ان آیات اور اس سے چند پہلی آیات میں ذوالقرنین بادشاہ ( یعنی خورس) کے بعض واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ یاجوج و ماجوج اقوام جو شمالی ایشیا اور مشرقی یورپ کے علاقوں میں رہتی تھیں.ایشیا کی زرخیزی کی وجہ سے اس پر حملے کرتی تھیں.ذوالقرنین نے ان اقوام کے حملوں کو بڑی سختی سے روک دیا اور یہ اقوام ایشیاکے انتہائی شمال مغرب اور یورپ کے مشرق میں گھِر گئیں.اور ذوالقرنین نے اس امر کا انتظام کیا کہ ان اقوام کے ایشیا میں آنے کی صورت ہی نہ رہے.اور ان کے حملوں سے نجات کے لئے ایک دیوار بنادی.سورۂ کہف کی آیات جو اوپر لکھی گئی ہیں ان میں ذوالقرنین کے اس واقعہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین جب دوپہاڑوں کے درمیان پہنچا.تو اس نے ان کے وَرے کچھ ایسے لوگ پائے جو بمشکل اس کی بات سمجھتے تھے.انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین یاجوج و ماجوج یقیناً اس ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں پس کیا ہم لوگ آپ کے لئے کچھ خراج اس شرط پر مقرر کردیں کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک روک بنادیں.اس نے کہا کہ اس قسم کے کاموں کے متعلق میرے رب نے جو طاقت مجھے بخشی ہے وہ دشمنوں کے سامانوں سے بہت بہتر ہے.اس لئے تم مجھے اپنی طاقت کے مطابق مدد دو.تاکہ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک روک بنادوں.تم مجھے لوہے کے ٹکڑے لادو.چنانچہ وہ روک تیار ہونے لگی.یہاں تک کہ جب اس نے پہاڑی کی دونوں چوٹیوں کے درمیان دیوار بنادی.تو اس نے ان سے کہا کہ اب مجھے گلا ہوا تانبا لادو تاکہ میں اس کو اس میں استعمال کر کے اس کو مضبوط کردوں.پس جب وہ دیوار تیار ہوگئی تو یاجوج و ماجوج کے حملے رک گئے.نہ تو وہ اس دیوار پر چڑھ کر اس کو پھاند سکے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے، اس پر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ کام محض میرے رب کے احسان سے ہواہے پھر جب عالمگیر عذاب کے متعلق میرے رب کا وعدہ پورا ہونے پر آئے گا تو وہ اسے توڑ کر زمین کے برابر کردے گا اور میرے رب کا وعدہ ضرور پورا ہوکر رہنے والا ہے.(یعنی وہ موعود وقت آنے والا ہے جبکہ یہ قومیں جنوب مشرق کی طرف بڑھیں گی اور یہ دیوار بےکار ہو جائے گی.کیونکہ ان قوموں کا داخلہ سمندر کے ذریعہ
Page 364
سے ہونا تھا اور یہ دیوار ان کے لئے روک نہ ہو سکتی تھی ) پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ وقت آجائے گا توہم ان قوموں کو ایک دوسرے کے خلاف جوش سے حملہ آور ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور بگل بجایا جائے گا اور دنیا میں ہلچل مچ جائے گی.تب ہم ان سب کو اکٹھا کردیں گے.اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے.ان کے سامنے جن کی آنکھیں میرے ذکر یعنی قرآن کریم کی طرف سے غفلت کے پردہ میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے.تو کیا یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا سکیں گے ہم نے تو کافروں کی ضیافت کے لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے.تُو انہیں کہہ کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں سے آگاہ کریں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں.یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوشش اس دنیاوی زندگی میں ہی لگ گئی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں.اِن آیات سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانہ میں ترقی کرتے کرتے یاجوج و ماجوج دونوں قومیں دنیا کے ممالک پر قابض ہو جائیں گی اور پھر آپس میں ان کی رقابت شروع ہو جائے گی اور آخر کار دونوں کی آپس میں مڈبھیڑ ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے پر آگ برسائیں گی اور اپنی تباہی کا موجب بن جائیں گی.پھر فرمایا کہ وہ دونوں بڑی صنعتی قومیں ہوں گی اور عجیب درعجیب ایجاد یں کریں گی.لیکن دین اورخدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی طرف سے غافل ہوجائیں گی اور اس وجہ سے ان کی دنیوی اور علمی ترقی بےکار ہو جائے گی اور ان کو تباہی سے بچانہیں سکے گی.یہ پیشگوئیاں موجودہ زمانہ پر بالکل صادق آتی ہیں.اسلامی حکومت کا تنزل سترہویں صدی کے شروع میں ہوا ہے.اور اس کے بعد مغربی حکومتوں کی سیاسی رسہ کشی شروع ہوئی ہے اور سائنس کی ترقی ہوئی ہے اور فلسفہ اور مادیت نے مذہب پر حملے شروع کئے ہیں جس کے نتیجہ میں آخر مذہب بالکل بے کار ہو کے رہ گیا.مادیت نے خالص منطقی نکتوں کی اتباع کر کے اقتصادی تغیرات کی ایسی ایسی شکلیں پیش کیں کہ دنیا محو حیرت ہو گئی.اور انہی میں سے ایک نتیجہ کمیونزم ہے.دنیا کے پید اکرنے والے ایک خدا اور اس کے نظام کو چھوڑ کر میں سمجھ ہی نہیں سکتا کہ دنیا کمیونزم یا ناٹسی ازم سے ورے کسی اور دلیل کو تسلیم کر سکتی ہو.خدا تعالیٰ اور اس کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے یاتو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ تمام انسان برابر ہیں اور دنیا کی سب چیزیں ان میں زور کے ساتھ برابر تقسیم کر دینی چاہئیں اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ ’’جس کی لاٹھی اس کی بھینس‘‘ طاقت ہی اصل چیز ہے جس کے پاس طاقت ہے وہی قابل ہے اور وہی دنیا کی
Page 365
نعمتوں کا مستحق ہے.آخر ان دونوں نظریوں کے سوا خالص عقل اور کیا نظریہ پیش کر سکتی ہے.صرف مذہب ہی ہے جو خدا اور اخلاق کو درمیان میں لا کر ایک درمیانی راہ پیش کرتا ہے.ورنہ عقل تو ان دونوں نظریوں کے سوا کسی جگہ نہیں ٹھہرتی.یاجوج و ماجوج کی لڑائی کے متعلق بائبل کی پیشگوئی یاجوج و ماجوج کے متعلق بائبل میں بھی پیشگوئی پائی جاتی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ کی ان دونوں طاقتوں ( یعنی یاجوج و ماجوج ) میں رقابت بڑھتے بڑھتے آخر لڑائی کا موجب ہو جائے گی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف آتشین اسلحہ کا استعمال کریں گی.چنانچہ حزقی ایل باب ۳۸ آیت ۱۸ تا ۲۲ میں آتا ہے :.’’ کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا قہر میرے چہرہ سے نمایاں ہوگا.خداوند خدا فرماتا ہے کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتشِ قہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا.یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اورآسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں.میرے حضور تھر تھرائیں گے اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی.اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا.خدا وند خدا فرماتا ہے اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی اور میں وبا بھیج کر اور خونریزی کر کے اسے سزا دوں گا اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں.شدت کا مینہ اور بڑے بڑے اَولے اور آگ اور گندھک برسائوں گا.‘‘ پھر باب ۳۹ آیت ۴ تا ۶ میں لکھا ہے :.’’ تو اسرائیل کے پہاڑوں پر اپنے سب لشکر اور حمایتیوں سمیت گر جائے گا اور میں تجھے ہر قسم کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کو دوں گا کہ کھا جائیں.تُو کھلے میدان میں گرے گا کیونکہ میں ہی نے کہا.خداوند فرماتا ہے اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا.‘‘ یاجوج و ماجوج کے متعلق قرآن کریم اور بائبل کی پیشگوئیوں میں ایک فرق قرآن کریم اور بائبل کی وہ آیات جو اوپر لکھی جا چکی ہیں ان سے ظاہرہوتا ہے کہ بائبل اور قرآن کریم دونوں یاجوج و ماجوج کی
Page 366
لڑائی کے متعلق متفق ہیں.لیکن قرآن کریم بائبل سے ایک بات زائد طور پر بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں تک ان کے سیاسی نظریوں کا سوال ہے وہ دونوں ہی اس لڑائی میں تباہ ہو جائیں گے اور دونوں میں سے کوئی بھی اپنی ہستی کو اس جنگ کے بعد زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے گا.احادیث سے معلوم ہوتاہے کہ جب دجّال اور یاجوج و ماجوج کے فتنے برپاہوں گے اور اسلام کمزور ہوجائے گا توا للہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت کے لئے مسیح موعود کو نازل کرے گااور وہ مشرق میں ظاہر ہوگا اور اس کے آنے کے بعد دجّال ہلاک ہو جائے گا.اس وقت مسلمانوں کے پاس مادی طاقت نہ ہوگی.لیکن مسیح موعود کی جماعت دعائوں اور تبلیغ کے ساتھ کام کرتی چلی جائے گی اور یاجوج و ماجوج آسمانی عذابوں کے ساتھ تباہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پھر اسلام کو غالب کر دے گا اور وہ دنیا کو کہے گا کہ تیری برکت تجھ میںپھر لوٹ آئے اور تھوڑا رزق لوگوں کے لئے کافی ہوگا.حرص مٹ جائے گی اور لوگ مادیت کی بجائے روحانیت کی طرف مائل ہوجائیں گے.یہاں تک کہ اسلام غالب ہو جائے گا.الغرض اسلام کو مٹانے کے لئے جو خطرناک فتنے آخری زمانے میں پیدا ہونے والے تھے سورۂ لہب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اور ان کے انجام کے متعلق پیشگوئی فرمائی ہے اور کہا ہے تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ.یعنی اسلام کے خلاف آگ بھڑکانے والی اقوام جو آخری زمانہ میں پیدا ہوں گی.اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو تباہ کرے گا.جیسا کے حل لغت میں لکھا جا چکا ہے تَبَّ کے معنے برباد ہونے اور ہلاک ہونے کے ہیں.اور جب کسی کا مقصد حاصل نہ ہو اس وقت بھی تَبَّ کا لفظ استعمال کرتے ہیں.مفسرین نے تَبَّتْ کے معنے صَفِرَتْ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ کے بھی کئے ہیں.یعنی ہر قسم کی خیرو برکت سے خالی رہنا.(البحر المحیط سورۃ اللہب) یَدٌ کے معنے ہاتھ کے بھی ہیں اور عزت و رتبہ.قوت و طاقت اور غلبہ و بادشاہت کے بھی ہیں.اسی طرح یَد کا لفظ جماعت پر بھی بولا جاتا ہے.پس تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ کے معنے ہوں گے.۱.ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے.۲.ابو لہب کے دونوں جتھے برباد ہوگئے اور ان کو ان کا مقصد حاصل نہ ہوا.۳.ابو لہب کی عزتیں، قوتیں، بادشاہت اور غلبہ سب ختم ہوگئے.۴.ابو لہب کے ساتھ تعلق رکھنے والی دونوں جماعتیں ہر قسم کے نفع اور خیر سے محروم رہیں.
Page 367
ابولہب سے مراد مغربی اقوام ابولہب کے لفظی معنے ہیں شعلے کا باپ.لیکن محاورے میں اس کے معنے ہوں گے وہ وجود جو ایسی چیزوں کا موجد ہو جن سے شعلے اور آگ پیدا ہو یا وہ وجود جس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ شعلوں کی لپیٹ میں آجائے گا.مفسرین کہتے ہیں کہ لفظ ابو لہب سے چہرے کا سرخ و سفید رنگ بھی مراد ہو سکتا ہے.جیسا کہ ہم اوپر اشارۃً ذکر کر آئے ہیں کہ سورۃ تبت میں ابو لہب سے مراد کوئی ایک شخص نہیں بلکہ اس سے مراد وہ قوم ہے جو آخری زمانہ میں دنیا پر غلبہ حاصل کرکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف آگ بھڑکائے گی.یا وہ ایسی ایجادیں کرے گی جس سے شعلے اور آگ پیدا ہو اور پھر یہ قوم اپنی ہمسایہ قوموں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر اپنے جتھہ کو مضبوط کرے گی اور یہ قومیں اس کے ہاتھ کی مانند ہوں گی.ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں دوہی جتھے ایسے ہیں جو کہ اسلام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف متحد ہیں.ایک جتھہ بعض مغربی طاقتوں پر مشتمل ہے اور ایک جتھہ بعض مشرقی طاقتوں اور ان کے ساتھیوں کا ہے.ابو لہب سے مراد یہ دونوںجتھے ہیں.یہ ظاہر میں بھی ابولہب ہیں کہ ان کے رنگ سرخ و سفید ہیں اور باطن کے لحاظ سے بھی کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم ایجاد کر رہے ہیں.جن کا نتیجہ آگ اور شعلے ہیں.اور اس لحاظ سے بھی ابو لہب ہیں کہ یہ انجام کار جنگ کی آگ کی لپیٹ میں آنے والے ہیں اور چونکہ ان لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خطرناک لٹریچر پیدا کر کے ایک آگ لگا دی ہے اس لئے بھی وہ ابو لہب کہلانے کے مستحق ہیں.تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ میں تَبَّتْ ما ضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے.لیکن عربی زبان میں جب کوئی امر یقینی اور قطعی طور پر ہونے والا ہو تو اس کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں.گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ تم یہ سمجھو کہ یہ کام ہو چکا.پس تَبَّتْ کے معنے اس جگہ پر یہ ہوں گے کہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ تباہ ہو جائیں گے اور ان کا یہ مقصد کہ اسلام کو مٹادیں حاصل نہ ہوگا.پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ آیت زیر تفسیر میں پہلے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کی تباہی کا ذکر ہے اور پھر اس کی اپنی تباہی کا.اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابو لہب کا نام پانے والی اقوام یعنی مشرقی اور مغربی طاقتیں دونوں پوری کوشش کریں گی کہ مختلف ممالک کو اپنے ساتھ ملالیں اور وہ ممالک ان کے ساتھ مل بھی جائیں گے اور ان کے لئے بطور ہاتھوں کے ہوجائیں گے.اور ابو لہب کہلانے والی اقوام ان جتھوں پر فخر کریں گی اور ان کو اپنی طاقت شمار کریں گی.لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ پہلے تویہ مویّدین تباہ ہوں گے اور پھر وہ وجود جو ابو لہب کہلانے کا مستحق ہوگا اور ان قوموں کا نقطۂ مرکزی ہو گا وہ تباہ ہوگا.
Page 368
ایک لطیف بات جو اس جگہ قابل ذکرہے وہ یہ ہے کہ احادیث میں جہاں اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریکات کو بیان کیا گیا ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان فتنوں کے وقت اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو نازل کرے گااور وہ ان فتنوں کا مقابلہ کریں گے.لیکن دعائوں سے.کیونکہ لَا یَدَانِ لِاَحَدٍ لِقِتَالِھِمْ.(مشکوٰۃ کتاب الفتن باب العلامات) ان اسلام کے مخالف لوگوں کا مقابلہ مادی ہتھیاروں سے نہ ہو سکے گا.اس لئے کہ مسلمانوں کی حالت ضعف و کمزوری کی ہوگی.لیکن اللہ تعالیٰ مسیح موعودؑ کی دعائوں کو سنے گا اور ایسے سامان پیدا کردے گا کہ جس طرح نمک پانی میں گُھل جاتا ہے.اسی طرح یہ اسلام کی مخالف اقوام آپس میں لڑکر تباہ ہو جائیں گی.قرآن کریم نے ابولہب کا نام پانے والی اقوام کے مویّدین کو بھی ہاتھوں سے تعبیر کیا ہے.اور فرمایا ہے تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ اور حدیث میں بھی جہاں آخری زمانہ میں پیدا ہونے والے فتنوں کا ذکر ہے وہاں یَدَانِ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.یہ امر بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اُمت محمدیہ کے متعلق آخری زمانہ میں آنے والے ابتلائوں کا علم دے دیا تھا اور بتادیا تھا کہ سورۂ لہب میں جن اقوام کے خروج کی خبر دی گئی تھی ان کا مقابلہ ظاہری طاقت سے نہ ہو سکے گا.تبھی تو آپ نے فرما دیا کہ لَا یَدَانِ لِاَحَدٍ لِقِتَالِھِمْ.الغرض آیتتَبَّتْ يَدَاۤ اَبِيْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اسلام پر حملہ کرنے والی اقوام اور اس کی تائید میں اٹھنے والے لوگ سب تباہی کا منہ دیکھیں گے اور اسلام کو مٹا نہ سکیں گے.مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَؕ۰۰۳ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیںدیا اور نہ اس کی کوششوں نے (کوئی فائدہ ) دیاہے.حلّ لُغات.مَا اَغْنٰی.مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ.اَغْنٰى عَنْهُ کے معنے ہوتے ہیں.نَابَ عَنْہُ کوئی چیز اس کے قائم مقام ہوگئی.اور جب مَایُغْنِیْ عَنْکَ ھٰذَا کا فقرہ بولیں تو معنے ہوں گے اَیْ مَا یُـجْدِیْ عَنْکَ یعنی یہ چیز تمہیں نقصان سے بچانے کے لئے کوئی فائدہ نہ دے گی.نیز اَغْنیٰ عَنْہُ کَذَا کے معنے ہیں.نَـحَّاہُ وَبَعَّدَہٗ.اس نے اس کو کسی چیز سے دور کر دیا اور جب مَااَغْنٰی فُلَانٌ شَیْئًا کہیں تو معنے ہوں گے لَمْ یَنْفَعْ فِیْ مُھِمٍّ وَلَمْ یَکْفِ مَؤُوْنَۃً کہ ضرورت اور تکلیف کے وقت فلاں کچھ کام نہ آیا.(اقرب)
Page 369
کَسَبَ.کَسَبَ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں جَـمَعَہٗ.اس کو جمع کیا.اور جب کَسَبَ مَالًا وَّ عِلْمًا کہیں تو معنے ہوتے ہیں طَلَبَہٗ وَرَبِـحَہٗ مال وعلم کو حاصل کیا اور ان سے فائدہ اٹھایااور کَسَبَ لِاَھْلِہٖ کے معنے ہوتے ہیں.طَلَبَ الْمَعِیْشَۃَ.اپنے اہل وعیال کے لئے معیشت یعنی زندگی بسر کرنے کے سامان حاصل کرنے کی کوشش کی.(اقرب) اَلْکَسبُ.مَا یَتَحَرَّاہُ الْاِنْسَانُ مِـمَّا فِیْہِ اجْتِلَابُ نَفْعٍ وَّ تَـحْصِیْلُ حَظٍّ کَکَسْبِ الْمَالِ یعنی اَلْکَسْبُ کے معنے ہیں اس چیز کی تلاش کرنا جس میں کسی نفع کی امید ہو.جیسے مال وغیرہ کو تلاش کیا جاتا ہے.(مفردات) تفسیر.مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ میں مَا نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور مَا استفہامیہ بھی.مَا نافیہ ہونے کی صورت میں یہ معنے ہوں گے کہ ابولہب کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا اور مَا استفہامیہ کی صورت میں یہ معنے ہوں گے کہ ابولہب کا مال اس کے کس کام آئے گا یعنی وہ اس کو تباہی سے بچا نہ سکے گا.مفسرین نے کہا ہے کہ مَاکَسَبَ میں مَا موصولہ بھی ہو سکتا ہے اور مَا مصدریہ بھی.موصولہ ہونے کی صورت میں یہ معنے ہوں گے کہ وہ چیزیں بھی اس کے کام نہ آئیں گی جو اس نے محنت کر کے حاصل کی تھیں.اور مصدری معنے یہ بنیں گے کہ اس مال کا کمانا اس کے کام نہ آئے گا.پہلی آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ اسلام پر حملہ کرنے والی اقوام تباہ ہو ں گی اور نہ صرف خودتباہ ہوں گی بلکہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ اس لئے شامل ہوئے تھے کہ ان کو کچھ نفع ہو گا وہ بھی حسرت کے ساتھ تباہ ہوں گے اوراُن کو ان کا مقصد حاصل نہ ہوگا.اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اقوام بڑی مالدار ہوں گی اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایجادوں اور صنعتوں سے بہت مال پیدا کیا ہوگا بلکہ اپناراس المال دوسرے ملکوں میں لگا کر اور تجارت کے بہانے دوسرے ملکوں پر قبضہ کرکے ان ملکوں کا مال بھی اپنے قبضہ میں کر لیا ہوگا.مَالُہٗ میںلفظ مال نکرہ رکھا اور نکرہ عظمت شان پر دلالت کرتا ہے(علم الـمعانی التنکیر).گویا اس سے یہ اشارہ کیا کہ اس کا عظیم الشان مال بھی اس کو تباہی سے بچا نہ سکے گا.مَالُہٗ کے بعد مَا کَسَبَ کے الفاظ رکھے ہیں اور مَاکَسَبَ کے معنے ہیں.مَکْسُوْبُہٗ اس کا کمایا ہوامال.گویا ان اقوام کے مالوں کو دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے (۱) وہ مال جو اپنے ملکوں میں صنعتوں وغیرہ سے پیدا کریں گے.(۲) وہ مال جو دوسرے ملکوں سے حاصل کریں گے.یہ ظاہر ہے کہ یہ آیت مغربی اقوام پرپوری طرح صادق آتی ہے کیونکہ ایک طرف صنعتی ترقی سے وہ مالدار ہوگئی ہیں اور دوسرے طرف انہوں نے نہ صرف دوسرے ملکوں
Page 370
میں اپنا راس المال لگا کر ان کا مال چھین لیا.بلکہ اس بہانے سے انہوں نے کئی ملکوں پر بھی قبضہ کر لیا.مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ میں یہ دلیل کہ یہ سورۃ ایک شخص کے لئے نازل نہیں ہوئی مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ کے الفاظ بھی اس امر کی دلیل ہیں کہ سورۂ لہب کا نزول عبدالعزیٰ کے لئے قراردینا کسی طرح بھی درست نہیں.کیونکہ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ کے الفاظ مال کثیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں.اور عبدالعزیٰ کے پاس تو کوئی ایسا مال نہ تھا جو قابل ذکر ہو اور نہ وہ اپنے زمانہ میں مالدار سمجھا جاتا تھا.کسی کے پاس چند اونٹوں کا ہونا اس کو مالدار نہیں بنا سکتا.پس مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ کے الفاظ اپنی پوری شان کے ساتھ مغربی اقوام پر ہی صادق آتے ہیں.کیونکہ یہی وہ اقوام ہیں جو دنیا کی دولت مند اقوام سمجھی جاتی ہیں.مفسرین کے نزدیک مَا كَسَبَ سے مراد اعمال، کوششیں اور اولاد بھی ہو سکتی ہے.پس ان معنوں کے اعتبار سے یہ مفہوم ہوگا کہ ان قوموں کو اپنے جتھوں، اپنے اموال اور اپنی ایجادات پر بڑا ناز ہوگا.لیکن تباہی کے وقت یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی بلکہ یہی چیزیں ان کی تباہی کا موجب ہو جائیں گی.سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍۚۖ۰۰۴ وہ ضرور آگ میں پڑے گا جو (اسی کی طرح ) شعلے مارنے والی ہوگی.حلّ لُغات.يَصْلٰى.يَصْلٰى صَلٰی سے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور صَلَی النَّارَ کے معنے ہوتے ہیں قَاسٰی حَرَّھَا وَاحْتَرَقَ بِـھَا وَدَخَلَ فِیْـھَا.یعنی آگ کی گرمی کی تکلیف برداشت کی اور آگ میں داخل ہوااور اس میں جلا.(اقرب) نَارٌ.اَلنَّارُ تُقَالُ لِلَھِیْبٍ یعنی نار کا لفظ آگ کے شعلوں پر بھی اطلاق پاتا ہے.وَ لِلْحَرَارَۃِ الْمُجَرَّدَۃِ وَلِنَارِ جَھَنَّمَ اور گرمی پر بھی اور جہنم کی آگ پر بھی.وَلِنَارِ الْـحَرْبِ اور لڑائی کے لئے بھی نار کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے.(مفردات) پس سَيَصْلٰى نَارًا کے معنے ہوں گے وہ ضرور آگ میں پڑے گا یا وہ ضرور جنگ میں پڑے گا.تفسیر.جیسا کہ حل لغات میں بتایا گیا ہے نار کے معنے آگ کے ہیں اور نار سے مراد جنگ بھی ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے.كُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ.(المآئدۃ:۶۵) یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں نے جب بھی لڑائی کی آگ کو برانگیختہ کیا.اللہ نے اسے بجھا دیا.پس نَارٌ کا لفظ عربی
Page 371
محاورے میں جنگ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ کے معنے یہ ہوں گے کہ ابو لہبی تحریکیں ایک سخت جنگ میں ڈالی جائیں گی اور وہ ایسی جنگ ہو گی جو شعلوں والی ہو گی اور ایسی ہو گی جس کی مثال پہلے نہ ملتی ہوگی.کیونکہ نار نکرہ ہے اور نکرہ عظمت شان پر دلالت کرتا ہے.یہ ظاہر ہے کہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا نتیجہ سوائے آگ کے شعلوں اور شدید گرمی کے کیا ہو سکتا ہے.کیونکہ ان کے استعمال سے بیک وقت شہروں کے شہر آگ کی لپیٹ میں آسکتے ہیں.سَيَصْلٰى نَارًا میں جنگ کی پیشگوئی پس یہ آیت بتاتی ہے کہ ان اقوام کو ایک ہولناک جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا.اور یہ آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں گی.عربی زبان میں س اور سَوْفَ جب فعل پر داخل ہوتے ہیں تو زمانہ کی مقدار بتاتے ہیں کہ یہ فعل کب واقع ہو گا.س زمانہ قریب کے لئے آتا ہے اور سَوْفَ زمانہ بعید کے لئے.اس آیت میں سَيَصْلٰى فعل پر س داخل ہوا ہے جو زمانہ قریب پر دلالت کرتا ہے گویا اس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ قومیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگ بھڑکائیں گی اور آپ کے مذہب کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گی جس وقت ان کی کوششیں انتہا کو پہنچ جائیں گی تو اس کے بعد جلد ہی وہ لڑائی کی آگ میں جھونکی جائیں گی.چنانچہ دیکھ لو کہ مغربی تحریکیں اسلا م کے خلاف۱۹۱۴ء میں کمال کو پہنچیں اور اس کے معاً بعد ان کی آپس میں جنگ ہوگئی جو ۱۹۱۸ء میں ختم ہوئی اور پھر دوبارہ ۱۹۳۸ء میں اس کے نتیجہ میں پھر ایک جنگ ہوئی جو ۱۹۴۵ء تک چلی گئی اور ۱۹۴۵ء کے بعد ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی ایجاد ہوئی جس سے دنیا ایک اور تباہی کے کنارہ پر کھڑی ہے اور یہ زمانہ اس زمانہ کے بالکل قریب ہے جس میں ان مغربی اقوام کی کوششیں اسلام کے خلاف انتہا کو پہنچ گئی تھیں.وَّ امْرَاَتُهٗ١ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِۚ۰۰۵ اور اس کی بیوی بھی.جو ایندھن اٹھا اٹھا کر لاتی ہے (آگ میں پڑے گی).حلّ لُغات.حَطَب.اَلْـحَطَبُ.مَا اُعِدَّ مِنَ الشَّجَرِ شَبُوْبًا لِلنَّارِ.درخت کی لکڑیاں جو جلانے کے لئے تیار کی جاتی ہیں اور خشک کی جاتی ہیں ان کو حَطَب کہتے ہیں.یعنی ایندھن نیز اَلْـحَطَبُ کے معنے ہیں اَلنَّمِیْمَۃُ چغل خوری(اقرب).پس حَمَّالَۃَ الْحَطَبِ کے معنے ہوں گے ایندھن اٹھانے والی (۲) چغلخوری کرنے والی.تفسیر.اِمْرَاَۃٌ کے معنے عورت کے ہیں.لیکن یہ لفظ ایسے لوگوں کے لئے بھی استعمال ہوجاتا ہے جو کسی
Page 372
کے ماتحت ہوں اور قوت متاثرہ رکھتے ہوں.جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو فرماتا ہے اسْکُنْ اَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّۃَ.(البقرۃ:۳۶) کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو.اس آیت میں زوج سے مراد صرف بیوی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی مراد ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے متبع تھے.اور ان کی ہر بات کو تسلیم کرتے تھے.وَّامْرَاَتُہٗ حَمَّالَۃَ الْحَطَبِ سے مراد مغربی اقوام کے اندرونی مؤیّد پس وَّامْرَاَتُہٗ حَمَّالَۃَ الْحَطَبِ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب کے نام کی مستحق اقوام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اور لوگ بھی اپنے فائدے کے لئے شامل ہو جائیں گے جواُن کے لئے بطور ہاتھ کے ہوں گے.بلکہ بعض ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو ان کے اپنے ملکوں میں ہوں گے.اور اپنی حکومتوں کو شہ دلائیں گے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایسے کام کریںجن سے اسلام ختم ہوجائے.یعنی لٹریچر بھی لکھوائیں گے اوراُن کے خلاف جنگ کے لئے بھی اُکسائیں گے.گویا ایندھن بھی مہیا کریں گے اور اسلام کے خلاف چغلخوری بھی کریں گے اور غلط باتیں پیش کر کے لوگوں کو اسلام کے خلاف بھڑکائیں گے.فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍؒ۰۰۶ اس کی (بیوی کی ) گردن میںایک کجھور کا سخت بٹا ہوا رسہ باندھا جائے گا ( جو کبھی نہ ٹوٹے گا).حلّ لُغات.جِیْدٌ.جِیْدٌ.اَلْـجِیْدُ.اَلْعُنُقُ.جِیْدٌ کے معنے گردن کے ہیں.(اقرب) مَسَد.مَسَد: حَبْلٌ مِّنْ لِیْفٍ.کجھور کے پتوں کا بٹا ہوارسہ.وَقِیْلَ الْـحَبْلُ الْمَضْفُوْرُ الْمُحْکَمُ الْفَتْلِ.اور بعض کہتے ہیں کہ مَسَد اس رسہ کو کہتے ہیں جو خوب مضبوط بٹا ہوا ہو.اور ٹوٹ نہ سکے.اَلْمِحْوَرُ مِنَ الْـحَدِیْدِ.لوہے کی وہ سلاخ جس کے اردگرد چرخی گھومتی ہے.(اقرب) تفسیر.فِیْ جِیْدِھَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ سے مراد فِیْ جِیْدِھَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ کے معنے ہیں کہ وہ لوگ جو ابولہبی اقوام کے لئے بمنزلہ عورت کے ہیں.ان کے گلوں میں ایسی رسیاں ہیں جو ٹوٹ نہیں سکتیں.یعنی ان کی مخالفت اسلام کے خلاف اتنی شدید ہوگی کہ اس کو دور کرنا مشکل ہوگا.پھر اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بظاہر ان حکومتوں کی قومیں آزاد کہلائیں گی لیکن درحقیقت اپنے زمانہ کے رسم ورواج کی غلام ہوں گی.اور جب تک خدا تعالیٰ ان کو آزاد نہ کرائے وہ حقیقی آزادی حاصل نہیں کرسکیں گی.
Page 373
سُوْرَۃُ الْاِخْلَاصِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ الاخلاص.یہ سورۃ مکّی ہے وَھِیَ خَمْسُ اٰیٰتٍ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ او راس کی بسم اللہ سمیت پانچ آیات ہیں سورۃ اخلاص مکی بھی ہے اور مدنی بھی ابن مسعودؓ کے نزدیک سورۃ الاخلاص مکی ہے اور حسن، عطاء، عکرمہ اور جابر بھی یہی کہتے ہیں.ابن عباسؓ، قتادہ، ضحاک اور سدی کہتے ہیں کہ یہ سورۃ مدنی ہے.لیکن ابن عباسؓ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مکی ہے (فتح البیان تعارف سورۃ الاخلاص).اتقان میں ہے کہ بعض مفسرین نے ان ہردو قسم کی روایتوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ سورۃ الاخلاص کا نزول دو مرتبہ ہوا تھا.ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں.اتقان کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطیؒ کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے ہمارے نزدیک صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سورۃ کا نزول دو مرتبہ ہوا.ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینہ میں.حضرت ابن مسعودؓ بالکل ابتدائی صحابہ میں سے ہیںاور تفسیر میں ان کا پایہ بلندمانا جاتا ہے.ان کی روایت کو بغیر کسی دلیل کے ردّ نہیں کیا جا سکتا.دوسری طرف ابن عباسؓ ہیں گو انہوں نے مدینہ میں جا کر ہوش سنبھالی ہے اور ابتدائی سورتوں کے متعلق ان کا علم محض سماعی ہے لیکن ان کا مقام بھی بہت بلند سمجھا جاتا ہے ان کی بات بھی بلا وجہ رد نہیں ہو سکتی.پس بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک صحابی کی بات بغیر کسی مضبوط دلیل کے رد کریں.ہم ان مفسرین کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں.جن کی رائے یہ ہے کہ اس سورۃ کا نزول دو مرتبہ ہواہے.سورۃ الاخلاص کا زمانہ نزول مستشرقین یورپ کے نزدیک وہیری اپنی کتاب کمنٹری اَون دی قرآن میں لکھتا ہے کہ میور کے نزدیک یہ سورۃ بالکل ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے.اور نولڈ کے کے نزدیک یہ چوتھے سال کی نازل شدہ ہے.وہیری کا خیال ہے کہ میور کی رائے درست ہے کیونکہ اس کا سٹائل اس قسم کا ہے جیسا کہ بالکل ابتدائی نازل ہونے والی سورتوں کا ہے.ہمارے مفسرین اور مستشرقین یورپ میں یہ فرق ہے کہ مفسرین سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کی بنیاد تاریخ پر
Page 374
رکھتے ہیں.لیکن مستشرقین بجائے تاریخ پر بنیاد رکھنے کے مضمون سورۃ اس کی عبارت اور اس کے سٹائل سے نتائج اخذ کرتے ہیں.مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ قرآن کریم کے مضمون کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ اتنی عربی جانتے ہیں کہ اس کی عبارت سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں.زبان عربی سے اُ ن کی واقفیت اتنی کم ہے کہ ان کا آیاتِ قرآنیہ کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کی مکہ والی زبان ہے اور اس کی مدینہ والی،محض ایک ڈھکونسلا ہوتاہے.سورۃ الاخلاص کے متعدد نام اس سورۃ کے متعدد نام مختلف تفسایر میں مروی ہیں.اور یہ ناموں کی کثرت اس کے کثرت مضمون کی طرف اشارہ کرتی ہے.چنانچہ وہ نام یہ ہیں :.۱.سورۃ التفرید.کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور فرد ہونے اور تثلیث وغیرہ کی تردید اس سورۃ میں کی گئی ہے.۲.سورۃ التجرید.کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لاثانی ہونے کا اس میںبیان ہے.۳.سورۃ التوحید.کیونکہ توحید کا ایسا واضح بیان کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے.۴.سورۃ الاخلاص.کیونکہ یہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتی ہے.۵.سورۃ النجاۃ.کیونکہ اس بات پر پورا یقین رکھنے سے کہ خدا ایک ہے انسان نجات پاتاہے.۶.سورۃ الولایۃ.کیونکہ یہ سورۃ پورے علم اور عمل اور معرفت کا ذریعہ ہو کر انسان کو درجہ ولایت تک پہنچادیتی ہے.۷.سورۃ المعرفۃ.کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسی کلام کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے.چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کو سن کر فرمایا کہ اس شخص نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی.۸.سورۃ الجمال.حدیث شریف میں آیا ہے کہ اِنَّ اللہَ جَـمِیْلٌ یُّـحِبُّ الْـجَمَالَ کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا جمال کیا ہے.آپ نے فرمایا اس کا اَحَد، صَمَد، لَمْ يَلِدْ١ۙ۬ وَ لَمْ يُوْلَدْ ہونا.۹.سورۃ الْمُقَشْقِشَۃ.مقشقشہ کے معنے ہیں بری کرنے والی.جب کوئی بیمار شفا پاتاہے تو اہل عرب کہتے
Page 375
ہیں تَقَشْقَشَ الْمَرِیْضُ عَـمَّا بِہٖ.یعنی بیمار نے اپنی اس بیماری سے شفا پائی جس میں مبتلاتھا.چونکہ یہ سورۃ شرک اور نفاق سے انسان کو بری کر کے خدا تعالیٰ کا خالص بندہ بنادیتی ہے اس واسطے اس سورۃ کا نام مُقَشْقِشَۃ رکھا گیا ہے.۱۰.سورۃالمعوّذہ.کیونکہ احادیث میں آتاہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کے پاس تشریف لے گئے اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر پھونکا.اور ان کو یہ ہدایت کی کہ ان سورتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کریں.۱۱.سورۃ الصمد.کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت صمد کا ذکر آتا ہے جس میں اس بات کو بیان کیاگیا ہے کہ کائنات کاہر ذرہ اس کا محتاج ہے.۱۲.سورۃ الاساس.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اُسِّسَتِ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُوْنَ السَّبْعُ عَلٰی قُلْ ھُوَاللّٰہُ اَحَدٌ یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا قیام قُلْ ھُوَاللّٰہُ اَحَدٌ کی وجہ سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ آسمانوں اور زمین کی بربادی کا موجب ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَکَادُ السَّمٰوٰتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْہُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ(مریم:۹۱،۹۲) قریب ہے کہ آسمان اس گندے عقیدہ کی وجہ سے پھٹ جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہوجائیں اور یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا(الانبیآء:۲۳) کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوجاتا گویا توحید کا عقیدہ اس دنیا کی آبادی کی بنیاد ہے.۱۳.سورۃ المانعہ.کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے.حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا اَعْطَیْتُکَ سُوْرَۃَ الْاِخْلَاصِ وَھِیَ مِنْ ذَخَائِرِ کُنُوْزِعَرْشِیْ وَھِیَ الْمَانِعَۃُ تَمْنَعُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ نَفَحَاتِ النِّیْرَانِ کہ میں نے تمہیں سورۃ الاخلاص دی ہے اور یہ میرے عرش کے خزانوں کے ذخائر میں سے ایک ہے اور یہ عذاب قبر اور آگ کے شعلوں سے بچانے والی ہے کیونکہ جو سچی توحید پر قائم ہو جائے اس کو آگ چھو نہیں سکتی.۱۴.سورۃ المحضر.کیونکہ جب یہ پڑھی جائے تو فرشتے اس کو سننے کے لئے حاضر ہوتے ہیں.۱۵.سورۃ البراءۃ.یعنی آگ سے یا شرک سے محفوظ رکھنے والی چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ سورۃ پڑھتے سنا.تو آپ نے فرمایا اَمَّا ھٰذَا فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الشِّـرْکِ کہ یہ شخص تو شرک
Page 376
سے پاک ہوگیا.پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے سو مرتبہ اس سورۃ کو نماز میں یا اس کے علاوہ پڑھا تو وہ آگ سے محفوظ ہو گیا.۱۶.سورۃ المذکّر ہ.کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو یاد دلاتی ہے.۱۷.سورۃ النور.کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں.اِنَّ لِکُلِّ شَیْءٍ نُوْرًا وَّ نُوْرُ الْقُراٰنِ قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کہ ہر چیز کا ایک نور ہوتاہے اور قرآن کا نور قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ہے.۱۸.سورۃ الامان.کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توحید کو ماننے والا قلعہ میں داخل ہوجاتا ہے اور اس سورۃ میں توحید کا ذکر ہے پس یہ عذاب سے امن میں رکھنے والی ہے.۱۹.سورۃ المنفّرۃ.یعنی شیطان کو بھگانے والی.(تفسیر کبیر لامام رازی سورۃ الاخلاص) فضائل سورۃ اخلاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ کو ثلث قرآن قراردیا ہے.چنانچہ آپ فرماتے ہیں.مَنْ قَرَأَ قُلْ ھُوَاللّٰہُ اَحَدٌ فَکَاَ نَّـمَا قَرَأَ ثُلُثَ القُراٰنِ.(تفسیر کبیر لامام رازی سورۃ الاخلاص) یعنی جس نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا تو گویا اس نے قرآن کریم کے تیسرے حصہ کو پڑھا.نیز ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیَدِہٖ اِنَّـھَا لَتَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُراٰنِ.(روح الـمعانی سورۃ الاخلاص) یعنی وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کی قسم کھاکر کہتا ہوںکہ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصہ کے برابر ہے.اس سورۃ کے ثلثِ قرآن ہونے سے یہ مرا دنہیں کہ یہ سورۃ قرآن کریم کے حجم کا تیسرا حصہ ہے.بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کامضمون خاص اہمیت رکھتا ہے.قرآن کریم اور احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتاہے کہ آخری زمانہ میں دوبڑے فتنے پیدا ہونے والے تھے.ایک دجّالی فتنہ اور دوسرا یاجوج و ماجوج کا فتنہ.اور ان دونوں فتنوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کے ساتھ ٹکر لینی تھی.ایک فتنہ خدائے واحد کی بجائے تین خدائوں کاعقیدہ لئے ہوئے ہے یعنی خداباپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس.اور دوسرا فتنہ دہریت کا ہے.یعنی وہ سرے سے خدا کا منکر ہے.قرآن کریم نے ان ہر دو فتنوں کے عقائد کی تردید کی ہے اور صحیح عقائد کو بیان فرمایا ہے.قرآن کریم خدا باپ کی تعریف سے بھر اہوا ہے اور اسی طرح سے خدا باپ کے رب ہونے اور ایک ہونے کی تائید کرتا ہے.اور خدا روح القدس اور خدا بیٹے کی نفی پورے زور سے کرتا ہے.گویا قرآن کریم نے خدا باپ کی خدائی کو قائم کیا ہے اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی تردید کی ہے.اس لئے یہ صاف بات ہے کہ چونکہ خدا باپ کی تائید قرآن کریم
Page 377
کا تیسرا حصہ ہے، اس لئے سورۃ اخلاص بھی قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے.درحقیقت قرآن کریم کاکام توحید کو ثابت کرنا اور غلط عقائد کو مٹانا ہے.پس جب اس سورۃ نے نہایت جامع مانع الفاظ کے ساتھ مختصر طور پر وہ مضمون ادا کردیا جس سے غلط عقائد کا ابطال ہوتاہے اور توحید کی حقیقت کو بیان کر دیا.تو یہ سورۃ ثلث قرآن کیا بلکہ سارے قرآن کے برابر ہوگئی.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورۃ کو ثلث قرار دینا مبالغہ نہیں.بلکہ اس کے مضمون کی اہمیت کے پیش نظر ہے.چنانچہ اسی اہمیت کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم السور کے نام سے بھی یاد کیا ہے.(روح المعانی مقدمۃ سورۃ الاخلاص ) سورۃ الاخلاص کے ساتھ نزول کے وقت سترہزار فرشتے نازل ہوئے روایات میں آتا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے.(روح البیان سورۃ الاخلاص) یہ روایت بھی اس سورۃ کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے اس قسم کی روایات کے متعلق جن میں سورتوں کے ساتھ فرشتوں کے نزول کا ذکر ہوتا ہے،یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے نزول کے وقت کی حفاظت مراد نہیں ہوتی بلکہ نزول کے بعد کی حفاظت مرا د ہوتی ہے.اور وہ اس طرح کہ ہر سورۃ کسی خاص مضمون کے بارہ میں ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس میں پیشگوئیاں ہوتی ہیں جن کے پو را ہونے پراس سورۃ کی سچائی کا انحصار ہوتا ہے.یہ پیشگوئیاں بعض دفعہ طبعی تغیرات کے متعلق ہوتی ہیں او ربعض دفعہ انسانی اعمال کے متعلق.انسانی اعمال کے متعلق جو پیشگوئیاں ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہیںکہ جن کے عذاب کی ان پیشگوئیوں میں خبرہو.وہ اس عذاب کو ٹالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں.اور چونکہ بالعموم غیر معمولی طور پر مخالف حالات میں کی جاتی ہیں.اس لئے دنیوی سامانوں کے لحاظ سے ان کا پورا ہونا بظاہر ناممکن یا غیر اغلب نظر آتا ہے.اور اسی وقت ان کے پورا ہونے کی کوئی صورت پیدا ہوسکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کا انتظام کیا جائے پس جس سورۃ میں اس قسم کی پیشگوئیاں ہوں جن کے باطل کرنے کے متعلق زبردست قوموں نے زور لگانا ہو.ان کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ملائکہ کو جو دنیا کے مختلف کاموں پر بطور مدبر مقرر ہیں، ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسے سامان پیدا کریں کہ وہ پیشگوئیاں بغیر روک کے پوری ہوجائیں.گوسورۃ الاخلاص میں کوئی پیشگوئی نہیں.لیکن چونکہ اس میں توحید باری کا مضمون ہے اور جیسا کہ اوپر کی سطور میںبیان ہو چکاہے کہ توحید کے خلاف آخری زمانہ میں دوخطرناک فتنے اٹھنے والے تھے اور وہ ایسے فتنے تھے کہ اگر آسمانی فرشتوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے مٹانے کا انتظام نہ فرماتا تو اسلامی طاقتیں ان کا مقابلہ نہیں
Page 378
کرسکتی تھیں اور ان فتنوں کا مقابلہ مشکل تھا.پس اللہ تعالیٰ نے توحید کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتوں کو لگا دیا تاکہ جہاں دجّالی فتنہ اور یاجوج و ماجوج کا فتنہ توحید کے خلاف نبر د آزما ہو اور پورے سازو سامان کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو.وہاں ان کے مٹانے کے لئے فرشتے آسمان سے اتریں اور مخالف حالات میں توحید کو دنیا پر قائم کردیں اور شرک اور دہریت کا قلع قمع ہو جائے اور جس طرح سے خدا تعالیٰ کی بادشاہت آسمان پر ہے زمین پر بھی قائم ہوجائے.اس سورۃ کے فضائل کے متعلق جو روایات بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک روایت حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری مسجد قبا میں نماز پڑھا یاکرتے تھے.جب بھی وہ کوئی سورۃ نماز میں پڑھتے تو اس سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے اور اس کے پڑھنے کے بعدپھر کوئی اور سورۃ پڑھتے.مقتدیوں نے کہا کہ جب ایک رکعت میںایک سورۃ پڑھنی کافی ہے تو دوسری سورۃ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے.اس پر انصاری نے کہا کہ میں تو سورۃ الاخلاص کو پڑھنا نہیں چھوڑسکتا خواہ مجھے امامت سے فارغ کردو.اور چونکہ اس محلہ میں افضل ترین شخص نماز پڑھانے کے لئے وہی تھے اس لئے ان کو امامت سے الگ نہ کیا گیا.ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محلہ میں تشریف لے گئے تو آپ کی خدمت میں معاملہ پیش کردیا گیا.تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری شخص سے اس سورۃ کو ہر رکعت میں پڑھنے کی وجہ دریافت کی تو اس صحابی نے جواب دیا اِنِّیْ اُحِبُّـھَا یعنی میں اس سورۃ کے مطالب سے محبت رکھتا ہوں.کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی توحید کو لئے ہوئے ہے.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبُّکَ اِیَّاھَا اَدْخَلَکَ الْـجَنَّۃَ(فتح البیان سورۃ الاخلاص).کہ تمہارے اس سورۃ سے محبت کرنے نے تم کو جنت میں داخل کر دیا.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتاہے کہ انسان اگر خالص توحید پر قائم ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل رکھے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتاہے.اسی طرح روایات میں آیا ہے.جَآءَ رَجُلٌ اِلَی النَّبِیِّ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَشَکَا اِلَیْہِ الْفَقْرَ فَقَالَ اِذَا دَخَلْتَ بَیْتَکَ فَسَلِّمْ اِنْ کَانَ فِیْہِ اَحَدٌ وَّ اِنْ لَّمْ یَکُنْ فِیْہِ اَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلٰی نَفْسِکَ وَاقْرَءْ قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ مَرَّۃً وَّاحِدَۃً.(روح البیان سورۃ الاخلاص) یعنی ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی محتاجی کی شکایت کا ذکر کیا.آپ نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میںکوئی موجود ہو تو اس کو السلام علیکم کہا کرو.اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اپنے نفس پر سلام بھیجو اور اس کے بعد قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ ایک دفعہ پڑھو.روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے
Page 379
آپ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا.چنانچہ اس کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ اس کی غربت دور ہوگئی بلکہ اس کے پاس روپیہ اور مال کی اتنی کثرت ہوگئی کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور ہمسایوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا.حقیقت یہی ہے کہ جب انسان کو علم ہو کہ ایک خداہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے وہ میرے کام میں برکت ڈال سکتا ہے تو اس پر توکل کرے گا اور اسی کے حضور جھکے گا.اور جب محنت اور دعا کسی کے اندر جمع ہوجائیں تو اس کی مشکلات دو رہوجاتی ہیں.اوراس روایت میں محنت، توکل اور دعا کا سبق سکھایا گیا ہے.بخاری، ابودائود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت عائشہؓ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر میں لیٹتے تو آپ دونوں ہتھیلیاں جمع کرتے اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھنے کے بعد ہتھیلیوں میں پھونکتے اور پھر سارے بدن پر مَل لیتے اور یہ فعل آپ تین مرتبہ کرتے.(روح المعانی تفسیر سورۃ الفلق) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سورتوں کو اکٹھا پڑھنے اوران کے ذریعہ دعا کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ان تینوں سورتوں کا جو قرآن مجید کے آخر میں رکھی گئی ہیں گہرا اشتراک ہے.سورۃ الاخلاص میں توحید کا مل کا ثبوت ہے اور دوسری دوسورتوں میں دعائوں کا ذکر ہے.اور یہ ظاہر ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ ایک خدا ہے جو ساری احتیاجوں کو پورا کرتا ہے اور ہر خیر کے دینے اور ہر شر سے حفاظت میں رکھنے پر قادر ہے تو اس کی توجہ کبھی دعا کی طرف مبذول نہیں ہوگی مثلاً اگر ایک کتا ہمیں کاٹنے کے لئے دوڑے تو جب تک ہمیں اس کے مالک کا پتہ نہ ہو ہم کس طرح کتے کو روکنے کے لئے کسی کو بلا سکتے ہیں.ہاں اگر ہمیں اس کے مالک کا علم ہوجائے تو ہم فوراً اسے آواز دے کر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو تمہارا کتا ہمیں کاٹتا ہے.اِسے ہٹائو.اسی طرح جب ہمیں علم ہوجائے کہ ایک ہستی ایسی ہے جس سے ہماری تمام ضروریات وابستہ ہیں.اوروہ اتنی طاقتور ہے کہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرسکتی ہے.تو پھر ہمارا دل دعا کی طرف خودبخود راغب ہو جائے گا.پس سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں طبعی ترتیب ہے.سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ جیسی قادر ہستی کا علم دیا گیا ہے اور اس کے بعد قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں ہمیں بتایاگیا ہے کہ ہمیں یہ دعاکرنی چاہیے کہ اے خدا ہر مخلوق تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے اس لئے تجھی سے ہم پناہ مانگتے ہیں.انسان ایک چیز کا نام لے کر نہیں کہہ سکتا کہ فلاں فلاں چیز سے مجھے بچائیے مثلاً ہزاروں بیماریاں ہیں.سردرد ہے.پھر سردرد کی کئی قسمیں ہیں.جن کا ڈاکٹروں کو بھی علم نہیں.کیونکہ اگر سردرد کی ہر قسم کا ڈاکٹروں کوعلم ہو تو پھر درد اچھا کیوں نہ ہو جائے اسی طرح بخاروں کی کئی قسمیں ہیں.اگر
Page 380
سارے بخاروں کا ڈاکٹروں کو علم ہو توپھر بخار کے سارے مریض کیوں اچھے نہیں ہوجاتے.ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملیریا ہے لیکن اب طبّی ترقی کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ ملیریا کی بھی کئی قسمیں ہیں.اور جن مچھروں سے ملیریا پیدا ہوتا ہے وہ بھی کئی قسم کے ہیں (The Encyclopedia Britanica, under word "Malaria").پس جب سارے بخار ڈاکٹروں سے اچھے نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ ملیریا کی بھی کئی قسمیںہیں جن کا ابھی تک پتہ نہیں لگا.ہومیو پیتھک والے تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کے بخار کی قسم الگ ہوتی ہے.یعنی زید کا بخار الگ قسم کا ہوتاہے بکر کا الگ قسم کا.پھر زید کا ملیریا ایک وقت میں ایک قسم کا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں دوسری قسم کا.مثلاً جب وہ ساگ کھاتا ہے تو ملیریا الگ قسم کا ہوتا ہے اور جب کباب کھاتا ہے تو اور قسم کا.غرض حقیقت یہ ہے کہ نہ بیماریوں کا احاطہ کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی اور شے کا.اس لئے فرمایا دعا کرو کہ خدایا ہمیں تو ہر چیز کا علم نہیں اس لئے تو ہی ہربرائی سے ہمیں بچا.پھر سورۃ الفلق کے بعد سورۃ الناس رکھ دی.اور اس میں یہ نہیں بتایاکہ مجھے زید کے شر سے پناہ دے یا بکر کے شر سے محفوظ رکھ.بلکہ فرمایا کہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ.خواہ وہ کسی زبردست کی طرف سے، ملک کی طر ف سے یا کسی افسر کی طرف سے ہو.او ریہ دعا اس وقت تک دل سے نہیں نکل سکتی جب تک کوئی شخص اَللّٰہُ اَحَدٌ کا قائل نہ ہو.قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کا گہرا اشتراک پس ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی آخری تین سورتوں کا باہم جوڑ اور اشتراک ہے اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے توحید کو سمجھنا چاہیے اس کے بعد دعائے کامل پیداہوگی اور جب دعائے کامل پیداہوگی توپھر شرکا خاتمہ ہو گا.قرآن کریم کی آخری تین سورتوں میں سورۃ فاتحہ کا مضمون دہرایاگیا ہے یہ امر بھی یادرکھنا چاہیے کہ یہ تینوں سورتیں (یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) سورۃ فاتحہ کے مضمون پر مشتمل ہیں.پس جس طرح سورۃ فاتحہ سے قرآن کریم شروع کیا گیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ختم بھی سورۃ فاتحہ پرہی کیا ہے.گویا وہ سارا مضمون جو سورۃ فاتحہ میں بیان کیا گیا تھا آخر میں آکر اسے دہرا دیا گیا ہے جس طرح استاد آخر میں سبق کو دہرادیتا ہے.سبق شروع کرنے سے پہلے وہ بیان کردیتا ہے کہ آج یہ مضمون شروع ہوگا.پھر آخر میں اس کاخلاصہ بیان کرکے بتاتا ہے کہ یہ مضمون ہم نے آج ختم کیا ہے.گویا سورۃ فاتحہ میں جن مضامین کی طرف توجہ دلائی گئی تھی.قرآن کریم میں ان کا حل کرنے کے بعد آخر میں ان کا خلاصہ کر کے بتایا ہے کہ ہم نے یہ بیان کیا ہے اسے یاد رکھنا.
Page 381
سبب نزول اس سورۃ کے شان نزول کے متعلق تین قسم کی روایات بیان ہوئی ہیں.پہلی روایت یہ آتی ہے کہ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یَامُـحَمَّدُ اُنْسُبْ لَنَا رَبَّکَ.یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے لئے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں.چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کی.اور بتایا کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی برابری کرنے والا ہے.(درمنثورسورۃ الاخلاص) یہ روایت مختلف طریقوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے.بعض روایات میں یہ بیان ہواہے کہ ایک اعرابی نے یہ سوال کیا تھا اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ سوال قریش مکہ نے کیا تھا.بہرحال سوال ایک ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اُنْسُبْ لَنَا رَبَّکَ یعنی اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں.ظاہر ہے کہ یہ روایت اپنے اندر کوئی صداقت نہیں رکھتی.کیونکہ یہ سوال عقلاً تبھی ہو سکتا ہے جب ان بتوں کا کوئی نسب نامہ ہوتا جن کی مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے.جب بتوں کاکوئی نسب نامہ تھا ہی نہیں تو مشرکین یہ سوال کر ہی کیسے سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ بیان کیا جائے.پس عقلاً سوال قریش مکّہ سے ہونا بعید ہے.دوسری روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ خیبر کے یہود آئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ خَلَقَ اللّٰہُ الْمَلٰٓىِٕكَةَ مِنْ نُّوْرِ الْـحِجَابِ وَاٰدَمَ مِنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ وَاِبْلِیْسَ مِنْ لَھَبِ النَّارِ وَالسَّمَآءَ مِنْ دُخَانٍ وَالْاَرْضَ مِنْ زَبَدِ الْمَآءِ فَاَخْبِرْنَا عَنْ رَّبِّکَ.یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پید اکیا اورآدم کو مٹی سے اور ابلیس کو آگ کے شعلے سے اور آسمان کو دخان (گیسز) سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے.پس ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا ہوااو ر کس چیز سے پیداہوا؟ روایت میں آتا ہے کہ یہ سوال سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا.یہاں تک کہ جبریل سورۃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ لے کر اترے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کے سوال کا جواب دیا.( در منثور سورۃ الاخلاص) اگر اس روایت پر ذرا غور کیا جائے تو عقلی طور پر وہ سوال جو یہود کی طرف منسوب کیاگیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا ناممکن معلوم ہوتاہے کیونکہ یہود اللہ کی ہستی کو مانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق تو ہے لیکن یہ سوال اس کے متعلق نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خود کس چیز سے پیداہوا.ہاں اس کی صفات کے متعلق سوال ہوسکتا ہے کہ اس کے اندر کو ن کون سی صفات پائی جاتی ہیں.پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ یہود کا سوال سن کر خاموش ہوگئے یہ بھی عقلاً درست نہیں.کیونکہ اس سوال تک قرآن کریم کا بیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا.اور اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سکتے تھے.یہود کا سوال کوئی ایسا مشکل نہ تھا
Page 382
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر خاموش ہوجاتے.پس یہ شان نزول جو سورۃ الاخلاص کا بیان کیا جاتا ہے عقلاً درست معلوم نہیں ہوتا.تیسری روایت یہ آتی ہے کہ یہ سوال عیسائیوں کی طرف سے تھا.جب وفد نجران مدینہ میں آیا تو انہوں نے کہا.صِفْ لَنَا رَبَّکَ اَمِنْ زَبَرْجَدٍ اَوْ یَاقُوْتٍ اَوْ ذَھَبٍ اَوْ فِضَّۃٍ فَقَالَ اِنَّ رَبِّیْ لَیْسَ مِنْ شَیْءٍ لِاَنَّہٗ خَالِقُ الْاَشْیَائِ فَنَزَلَتْ قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ.(تفسیر کبیر لامام رازی سورۃ الاخلاص ) یعنی ہمارے لئے اپنے رب کا حال بیان کرو کہ وہ زبرجد کا بناہواہے یا یاقوت کا یا سونے کا یا چاندی کا.اس سوال کو سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بناہوا نہیں ہے کیونکہ یہ سب اس کی مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے.بعد ازاںسورۃ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ نازل ہوئی جس میں عیسائیوں کے سوال کا جواب بیان ہواہے.یہ روایت بھی عقلاً درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ عیسائی بھی خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں.گو اس کے ساتھ بیٹا خدا اور روح القدس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں.لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باپ خدا سونے چاندی اور یاقوت وغیرہ کا مجسمہ نہیں.پس ان کی طرف سے اس سوال کا ہونا عقلاً بعید ہے.الغرض سورۃ الاخلاص کے متعلق جوروایات اس کے سبب نزول کے متعلق بیان کی جاتی ہیں وہ محض قیاسی ہیں.او رکوئی بھی ان میں سے ایسی وجہ نہیں جس کی بنا پر اس عظیم الشان سورۃ کا نزول ہوتا.اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اپنی توحید کا اعلان فرمایا تاکہ ہر چھوٹا اور بڑا مسلمان اس کو سمجھ لے اور ذہن میں اس کو مستحضر رکھے اور ہر مجلس میں اس کا اعلان کرنا اپنا فرض خیال کرے.غالباً جن لوگوں نے شان نزول کے متعلق روایات بیان کی ہیں ان کو اس کا شان نزول ڈھونڈنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی ہے کہ اس سورۃ سے پہلے قُلْ کا لفظ استعمال ہواہے جس سے یہ شبہ ہوسکتا ہے کہ یہ کسی سوال کا جواب ہے.حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہواہے کسی سوال کے جواب میں ہواہے.بلکہ عام طور پر جہاں پر یہ لفظ آتا ہے وہاں یہ حکم ہوتاہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُمت کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اس کے بعد بیان ہونے والے امر کا پوری طرح لوگوں میںاعلان کرتے جائیں اور اس کے بیان کرنے میں کوتاہی نہ کریں.
Page 383
بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۰۰۱ (میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتاہوں) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ۰۰۲ (ہم ہر زمانہ کے مسلمان کو حکم دیتے ہیں کہ ) تُو (دوسرے لوگوں سے ) کہتا چلا جا کہ (پکی اوراصل ) بات یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلاہے.حلّ لُغات.ھُوَ :.ھُوَ اسم ضمیر ہے جو واحد مذکر غائب کے لئے استعمال ہوتاہے.اردو میں اس کے معنے ’’وہ ‘‘ کے ہوتے ہیں لیکن قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ میں ھُوَ وہ کے معنوں میں نہیں ہے.کیونکہ وہ کے معنے تب ہوتے جب ھُوَ سے پہلے کسی ایسی چیز کا ذکر ہوتا جس کے قائم مقام وہ بن جاتا.یہاں پر ھُوَ ضمیر شان ہے.اور اس کے معنے ہیں.حق یہ ہے، سچ یہ ہے، شان یہ ہے.اصل پکی بات یہ ہے کہ اللہ اَحَدٌ ہے.اَللّٰہُ :.اللہ اس ذات پاک کا نام ہے جو ازلی ابدی اور الحی القیوم ہے اور مالک و خالق اور رب سب مخلوق کا ہے اور اسم ذاتی ہے نہ کہ اسم صفاتی.عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں اس خالق ومالک کل کا کوئی ذاتی نام نہیں پایا جاتا.صرف عربی میں اللہ ایک ذاتی نام ہے جو صرف ایک ہی ہستی کے لئے بولا جاتا ہے اور بطور نام کے بولا جاتا ہے.اللہ کا لفظ اسم جامد ہے مشتق نہیں ہے.یعنی نہ یہ اور کسی لفظ سے بناہے اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنا ہے.اَحَدٌ:.عربی زبان میں دو الفاظ ’’ایک ‘‘ کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں.ایک ’’واحد‘ ‘ کا لفظ اور دوسرا’’اَحَدٌ‘ ‘ ہے.اَلْوَاحِدُ کے متعلق لغت میںلکھا ہے اَلْوَاحِدُ اَوَّلُ الْعَدَدِ یُقَالُ وَاحِدٌ، اِثْنَانِ، ثَلَاثَۃٌ.(اقرب) یعنی عربی زبان میں واحد وہ عدد کہلاتا ہے جس سے آگے اور عدد چلتے ہیں یعنی دو، تین، چار.لیکن اَحَدٌ کا لفظ عربی میں اس وقت بولا جاتا ہے جب دوسرے عدد کا ذہن میں کوئی مفہوم ہی پیدا نہ ہو.مثلاًاردو میں اس کی مثال لفظ ’’اکیلا‘‘ ہے اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں Oneness گویا جب ہم کہتے ہیں ایک تو اس کے ساتھ دو، تین، چار، پانچ کا مفہوم بھی ذہن میں آتا ہے.لیکن جب کہتے ہیں اکیلاتو اس کے آگے دو کیلا، تکیلا کوئی لفظ نہیں ہوتا.اقرب میں ہے کہ اَلْفَرْقُ بَیْنَ الْاَحَدِ وَالْوَاحِدِ اَنَّ الْاَحَدَ اِسْـمٌ لِّمَنْ لَّا یُشَارِکُہٗ شَیْءٌ فِیْ ذَاتِہٖ
Page 384
وَالْوَاحِدُ اِسْـمٌ لِّمَنْ لَّا یُشَارِکُہٗ شَیْءٌ فِیْ صِفَاتِہٖ.(اقرب) یعنی احد اور واحد جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لئے احد کا لفظ استعمال ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت کو بیان کر تا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا اگر تصور کریں تو دوسری کسی ذات کا خیال بھی دل میں نہیں آتا.اور جب اللہ تعالیٰ کے لئے واحد کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں صفات کی وحدانیت مراد ہوتی ہے کہ وہ صفات میں واحد ہے یعنی اپنی صفات میں کامل ہے اوراس کے سوا کوئی اور وجود نہیں جو صفات کے لحاظ سے کامل ہو.پس قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کے معنے ہوں گے اعلان کردو کہ پکی اور اصلی بات یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے.تفسیر.جیسا کہ سورۂ لہب کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے.سورۂ لہب پر قرآن کریم کا مضمون ختم ہے گویا سورۃ لہب آخری سورۃ ہے.یہ ظاہر ہے کہ ہر شخص نہ قرآن کریم کے وسیع مطالب کو سمجھ سکتا ہے اور نہ ان پر پورا عبور حاصل کرسکتاہے اور نہ اس کو ذہن میں رکھ سکتا ہے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے فائدہ کے لئے یہ طریق اختیار کیا کہ آخرمیں سورۃ لہب کے بعد تین سورتوں میں سارے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کردیا.جیسے ایک قابل مصنّف کتا ب کو شروع کرنے سے قبل ان مضامین کو اختصاراً بیان کر دیتا ہے جو اس کتاب میں بیان کئے جانے ہیں اور کتاب کے آخر میں پھر اپنے مضامین کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے.بعینہٖ اسی طرح قرآن کریم کے ابتدا میں سورۃ فاتحہ کورکھا گیا ہے.اور اس میںاختصاراً ان مضامین کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے.جو قرآن کریم میں بیان کئے جانے تھے.پھر آخر میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں سارے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیا.گو ایک رنگ میں سورۃ الاخلاص بھی فی ذاتہٖ قرآن کریم کا مکمل خلاصہ ہے.کیونکہ قرآن کریم کے مضامین کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوجائے گا کہ ان مضامین کا نقطہ مرکزی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جائے اور اس کی صفات اور شان کو بیا ن کیا جائے.چنانچہ سورۃ الاخلاص میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کامل اور اس کی صفات اور شان کو بیا ن کردیا گیا ہے.گویاان معنوں میں سورۃ الاخلاص بھی قرآن کریم کا خلاصہ ہے.لیکن اگر آخری تینوں سورتوں میں بیان ہونے والے مضمون کو من حیث المجموع دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ تینوں سورتیں سورۃ فاتحہ ہی ہیں.گویا جس طرح سورۃ فاتحہ سے قرآن کریم کو شروع کیا گیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ختم بھی سورۃ فاتحہ پر کیا ہے اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم نے خود قرآن کریم کا خلاصہ کر دیا ہے اب ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس خلاصہ کو
Page 385
یا د رکھے، اپنی نسلوں کو اس کی وصیت کرے اور دنیا میں اس کا اعلان کرتا رہے یہاں تک کہ دنیاایک مرکزی نقطہ پر جمع ہوجائے.سورۃ الاخلاص کے شروع میں قُلْ کا لفظ لانے میں حکمت اور اس مقصد کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے قُلْ کا لفظ آخری تینوں سورتوں سے پہلے رکھ دیا.جس کے معنے یہ ہیں کہ یہ پیغام ہمارا آگے دوسرے لوگوں تک پہنچادو.جب دوسروں تک یہ پیغام پہنچے گا تو چونکہ وہ بھی قُلْ کا لفظ پڑھیں گے جس کے معنے ہیں.کہو.بیان کرو.ان پر بھی فرض ہوجائے گا کہ وہ اس کلام کو آگے دوسروں تک پہنچائیں.یہ ویسا ہی ہے جیسے آج کل لوگ خطوں میں لکھتے ہیں کہ جسے وہ پہنچے وہ آگے دس لوگوں تک وہی مضمون پہنچا دے گویا قرآن کریم اور اسلام کی تعلیم کاخلاصہ ان آخری تین سورتوں میں بیان فرما دیا اور واضح کر دیا کہ اے انسان جبکہ تو سارا قرآن پڑھ چکا.اب ہم تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے لئے ہے اور اسے لوگوں تک تم نے پہنچانا ہے.مگر چونکہ یہ ممکن نہیں کہ ہر انسان اس کے تمام مطالب پر حاوی ہو سکے اور نہ ہر شخص حافظ ہو سکتا ہے.اس لئے ہم تمہاری آسانی کے لئے اس کا خلاصہ بیان کردیتے ہیں.مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ قُلْ یعنی تم اس مفہوم کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو اور تم سے سننے والے کچھ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور وہ کچھ اور لوگوں کے یہاں تک کہ اسی طرح ہوتے ہوتے یہ مفہوم سب دنیا تک پہنچ جائے.گویا لفظ قُلْ کے ذریعہ ہر مسلمان اس بات کا پابند ہو جاتاہے کہ وہ اس مضمون کو دوسروں تک پہنچائے یہ نہیں کہ عمر بھر میںایک دفعہ اس پر عمل کردیا بلکہ قُلْ ھُوَاللّٰہُ اَحَدٌ کے جملہ کی بندش بتاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جس کسی کو ملے جس مجلس میں جائے اور جس مقام پر جائے وہاں پر اس کا اعلان اس کے مدّ ِنظر ہو.اور پھر جو اس اعلان کو سنیں وہ آگے دوسروں تک پہنچائیںحتی کہ یہ مضمون ساری دنیا تک پہنچ جائے اورشاید اسی بنا پر کسی نے اس رسم کا نام قُلْ رکھ دیا ہے جو موت کے بعد مسلمانوں میں ادا کی جاتی ہے.مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے ایک غیر احمدی عزیز فوت ہوئے.ان کے متعلقین نے مجھے بھی بلایا.میں بھی گیا.جب وہاں سب لوگ بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک مولوی صاحب نے پہلے کچھ پڑھا اس کے بعد گھروالوں نے لا کے ہاتھ میں قرآن کریم کا ایک نسخہ دیا.اس نے آگے دوسرے کے ہاتھ میں دیا.پھر اس نے میرے ہاتھ میں دے دیا میں اس وقت چھوٹا تھا اور ان امور سے بالکل ناواقف.اور مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ یہ کیابات ہے.جائز ہے کہ ناجائز.گو مجھے یاد ہے کہ میں دل میں کراہت کر رہا تھا آخر جب انہوںنے مجھے قرآن کریم
Page 386
دیا تو میں نے اسے لے کر سامنے رکھ دیا.کیونکہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مجھ سے کچھ چاہتے ہیں.اس پر کسی نے خود ہی وہ قرآن مجید اٹھا کر آگے کر دیا.یا شاید مجھے کہا کہ یہ آگے دے دو.میں نے کسی صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مرنے والے کو ثواب پہنچانے کا ایک طریق ایجاد کیا گیا ہے لوگوں نے سوچا کہ جو چیز بھی مرنے والے کے لئے صدقہ میں دیںگے وہ دس بیس یا پچاس سو روپیہ کی ہوگی اور اس لئے مرنے والے کو ثواب بھی محدود پہنچے گا اور شاید اس کے گناہوں کا کفارہ نہ ہو سکے.اس لئے انہوں نے یہ سوچا کہ قرآن کریم صدقہ میں دیا جائے.جس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا.اس خیال کو عملی شکل اب یہ دی جاتی ہے کہ ایک شخص قرآن کریم اپنے سے اگلے آدمی کو یہ کہہ کر کہ میں نے تیری مِلک کیا دے دیتا ہے اور وہ اگلے کو.اس طرح گویا کئی قرآن کریم صدقہ میں دے دیئے جاتے ہیں اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ اس طرح مرنے والے کو بے انتہا ثواب پہنچا ہوگا.اور بے انتہا گناہ اس کے معاف ہو گئے ہوں گے.شاید اس رسم کا نام قُلْ اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں بھی صدقہ کی چیز چکر کھا تی ہے.اگر مسلمان اس تعلیم پر جو اللہ تعالیٰ نے قُلْ کے لفظ میں ان کو دی ہے عمل کرتے تو یہ ذلت جو ان کی اس زمانہ میں ہورہی ہے کبھی نہ ہوتی.اور آج ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوتی.کتنی چھوٹی سی بات ہے مگر مسلمانوں نے اسے نظر انداز کردیا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقعہ پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایاتھا.اِنَّ اَمْوَالَکُمْ وَدِمَاءَکُمْ وَاَعْرَاضَکُمْ حَرَامٌ عَلَیکُمْ کَحُرْمَۃِ یَوْمِکُمْ ھَذَا فِیْ شَھْرِکُمْ ھٰذَا فِیْ بَلَدِ کُمْ ھٰذَا.پھرا س کے بعد فرمایا اَلَا لِیُبَلِّغِ الشَّاھِدُ الْغَائِبَ.(بخاری کتاب الـحج باب الـخطبۃ ایام منٰی) یعنی جو مسلمان حاضر ہیں، وہ سن لیں اور جو حاضر نہیں ان کو سننے والے یہ بات پہنچا دیں کہ تمہارے مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں جیسے اس دن کی، اس مہینہ کی، اور اس شہر کی حرمت ہے.میں نے جماعت میں یہ تحریک جاری کی تھی کہ جو دوست اس تعلیم کو سنیں وہ اسے آگے دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا.گویا یہ تحریک بھی دراصل قُلْ کی طرح ہی تھی.ایک سے دوسرے تک اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو قوم میں بیداری پیدا ہوتی ہے.الغرض قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ میں یہ کہا گیا ہے کہ اے مسلما ن جو ایمان لاتا ہے.ہماری ذات پر، ہمارے کلام پر اور اس میںسے بھی ہمارے قرآن پر.ہم تم سے کہتے ہیں کہ جائو اور لوگوں کو جا کر کہو کہ اسلام کی تعلیم کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے.
Page 387
قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ اور سورۃ فاتحہ کے مضامین کا اشتراک جیساکہ اوپر کی سطور میں اشارۃً بیان ہوچکا ہے قرآن کریم کی آخری تین سورتوں میں سورۃ فاتحہ کا مضمون بیان ہواہے.سورۃ الاخلاص میں اس طور پر کہ قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ جو ہے یہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے مضمون کی حال ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.توحید کا مل او رتوکل کامل پر دلالت کرتے ہیں.توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے جب انسان سمجھ جائے کہ اور کچھ ہے ہی نہیں.تو پھر خدا کے سوا وہ کسی پر سہارا نہیں کرسکتا.کسی مقام پر ڈاکٹر بھی ہو حکیم اور وَید بھی اور ہومیو پیتھک ڈاکٹر بھی تو ڈاکٹر کے علاج سے آرام نہ ہونے کی صورت میں تیماردار حکیم کی طرف بھاگے جاتے ہیں اور اس کی دوائی سے فائدہ نہ دیکھ کر وَید کی طرف اور پھر ہومیو پیتھک معالج کی طرف پھرایک ہی قسم کے ڈاکٹر ہی اگر ایک سے زیادہ ہوں تو کبھی گھبرا کر ایک کی طرف جاتے ہیں اور کبھی دوسرے کی طرف.مگرجب نظر ہی کوئی نہ آئے تو کوئی دوڑ دھوپ نہیں ہوتی.سورۃ الاخلاص میں توحید کامل اور توکل کامل تو اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اور اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ نے توحید کامل کا مضمون بیان کیا ہے یایوں کہو کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اور اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ نے توحید کامل اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ نے توکل کا مل کا مضمون بیا ن کیا ہے اور یہی مضمون قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ میں بیان کیا گیا ہے.فرمایا کہہ دے کہ اللہ ہی اَحَدٌ ہے.اَحَدٌ اس ذات کو کہتے ہیں جو ماسوا کو بھلا کر ہمارے سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے اور احد بھی.واحد کے معنے یہ ہیں کہ وہ سرچشمہ ہے تمام مخلوقات کا اور احد کے معنے ہیں کہ اس کے سامنے ہر چیز غائب ہوجاتی ہے.اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ میں یہی بیان تھا کہ لوگ کہتے ہیں باپ کا احسان ہے مگر ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا.سو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے.لوگ کہتےہیں کہ استاد کا احسان ہے مگر ہمیں تو کوئی استاد نظر نہیں آتا.سوائے اللہ تعالیٰ کے.سو ہم کہتے ہیں.اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.اسی طرح لوگ کہتے ہیں ہمسایہ کا احسان ہے مگر ہمیں تو سب احسان اللہ تعالیٰ کے ہی نظر آتے ہیں.اس کے سوا کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا.اس لئے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.سب تعریف اللہ ہی کی ہے.تو قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ میں اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ والا مضمون ہی بیان کیا گیاہے لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ میں بھی وہی ہے یعنی نہ کوئی اس سے پہلے ہے اور نہ پیچھے ہے.وہی وہی ہے.پھر وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًااَحَدٌ میں بھی وہی مضمون ہے.اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ سب چیزیں
Page 388
جب نظر آتی ہیں تو پھر یہ کہنا غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا نظر کچھ نہیں آتا.تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب چیزیںنظر آتی ہیں.مگران میں سے کوئی بھی خدا تعالیٰ کا کفو نہیں.یعنی وہ تو سب کچھ اپنے پاس سے دیتا ہے اور باقی لوگ جو کچھ دیتے ہیں خدا کے دیئے ہوئے میں سے دیتے ہیں.اپنے پاس سے نہیں دیتے.اس کے سوا سب محض واسطے ہیں خدا ان کے پیالے میں ڈالتا ہے تو وہ آگے پہنچادیتے ہیں.ماں کی چھاتیوں میں دودھ خدا تعالیٰ ڈالتا ہے اور وہ صرف واسطہ بن جاتی ہے.باپ کو خدا تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اولاد پرخرچ کردیتا ہے.توگویا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اور قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کا مضمون ایک ہی ہے.پھر اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کا مضمون اَللّٰہُ الصَّمَدُ میں آگیا ہے.صمد وہ ہے جو خود تو کسی کا محتاج نہ ہو مگر باقی سب اس کے محتاج ہوں اور وہ ان کی حاجتیں پوری بھی کرتا ہو.اِيَّاكَ نَعْبُدُ میں یہ مضمون آگیا کہ سب خدا کے محتاج ہیں اور نَسْتَعِيْنُ میں یہ مضمون آگیا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتاہے اور جب اس کے سوا کوئی حاجت پوری کر ہی نہیں سکتا تو ہر ایک کو مجبور ہو کر اسی کی طرف آناپڑتا ہے.پس ظاہر ہے کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص کے مضمون میں ایک اشتراک ہے.سورۃ الاخلاص ہے تو بہت مختصر لیکن اس میں کامل توحید کو پیش کیا گیا ہے.چنانچہ اس میںتین امور کو پیش کیا ہے.۱.خدا تعالیٰ کی ذات کو کہ وہ موجود ہے.۲.خدا تعالیٰ کے ذات میں منفرد ہونے کو یعنی یہ کہ وہ اکیلا ہے اور یہ کہ دویا تین خدا نہیں.۳.خدا تعالیٰ کے واحد فی الصفات ہونے کو.یعنی یہ کہ اس کی صفات میں کوئی ہمسر ی نہیںکرسکتا.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ تم کہہ دو کہ خدا کی ہستی کے متعلق تم مختلف خیالات میں مبتلا ہو.قسم قسم کی تھیوریاں ایجاد کرتے ہو.طرح طرح کے فلسفے اور نکتے معلوم کرتے ہو.لیکن خدا تعالیٰ کے متعلق جو یقینی بات ہے اس کا نقطہ مرکزی یہ ہے کہ اَللّٰہُ اَحَدٌ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ہر رنگ میں او رہر طرح اپنے وجود میں ایک ہی ہے نہ وہ کسی کی ابتدائی کڑی ہے اور نہ آخری سرا.نہ کسی کے مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کے مشابہ.اَحَدٌ کا لفظ اپنے اندر عجیب خصوصیت رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اس میں کسی رنگ میں دُوئی کا خیال نہیں پایا جاتا.باقی سب ہندسوں میں دُوئی کا خیال پایا جاتا ہے.حتی کہ واحد میںبھی اور اوّل میں بھی دُوئی پائی جاتی ہے.واحد کے معنے ہیں پہلا.یعنی دوسروں کی نسبت سے پہلا.اور نسبت دُوئی کو طلب کرتی ہے کیونکہ اس وقت تک کسی چیز کی نسبت نہیں قائم کی جا سکتی جب تک دُوئی نہ ہو.ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دایا ں ہے جب تک بایاں نہ ہو.اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے
Page 389
یہ شمال ہے جب تک جنوب نہ ہو.اسی طرح جوواحد ہے وہ دلالت کرتاہے کہ دوسرے ہوں مگر اَحَدٌ کے معنے ایک ہیں اور ایک دوسرے کی نفی کردیتا ہے.مگر ایک کے لفظ سے بھی وہ مفہوم ادا نہیں ہوسکتا جو اَحَدٌ میں پایا جاتاہے.لیکن چونکہ اس کے سوا کوئی اور لفظ اردو میں نہیں پایا جاتا.اس لئے ہم مجبور ہیں کہ ایک کا لفظ استعمال کریں.تو اَحَدٌ کے معنے ہیں وہ ذات جو ایسی ایک ذات ہے کہ جس کا تصور کریں تو دوسری کسی ذات کا خیال بھی دل میں نہ آسکے.پس اَحَدٌ وہ صفت ہے کہ جو سب خُلق سے منزّہ ہو اور درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اصل شان احدیت ہی ہے.کیونکہ خدا تعالیٰ مخلوق سے تعلق کے لئے نیچے اُترتا ہے تو اس کی صفات محدود ہوتی جاتی ہیں جیسے مثلاً سورج ہے اس کی چوڑائی آٹھ لاکھ میل ہے(Encyclopedia Brictanica under word "Sun") لیکن آنکھ کے مقابلہ میں آکر چھوٹا سارہ جاتا ہے.کیونکہ اگر اس کا عکس پوری جسامت میںہو تو آنکھیں دیکھ نہ سکتیں.پس جس طرح آنکھوں کے محدود ہونے کی وجہ سے جب تک سورج چھوٹا نہ ہو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اسی طرح خدا تعالیٰ جو اَحَدٌ کی شان رکھتا ہے اور اس کی اصل شان یہی ہے جب بندوں پر ظاہر ہوتاہے تو ایسا کہ ہم اسے دیکھ سکیں.اور خدا تعالیٰ کی وہ جلوہ گری کامل نہیں ہوتی.پس اللہ تعالیٰ کی اصل شان کو جو احدیت ظاہر کرتی ہے کوئی اور صفت بیان نہیں کرتی.حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دو قسم کا رب ہے.ایک رب الاحدیت اور ایک رب المخلوق.شان اوّل کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا.مگر دوسری شان محدود ہے.اسی طرح خدا تعالیٰ رحمان بھی دو قسم کا ہے وہ رحمانیت جو احدیت کے لحاظ سے ہے اور اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا.لیکن وہ رحمانیت جو بندوں سے تعلق رکھتی ہے اسے ہر عقل والا دیکھ سکتا ہے.یہی خدا تعالیٰ کی مالکیت کا حال ہے اور یہی اس کے علم کا.گویا بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی صفات محدودہیں.لیکن احدیت کی شان کے ساتھ تعلق رکھنے والی صفات محدود نہیں.انہی دو کیفیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق بڑے جھگڑے چلے آئے ہیں.بعض نے تو کہا ہے خدا نظر نہیں آتا.بعض نے کہا نظر آتا ہے.اس پر جھگڑنے لگ گئے.حالانکہ جنہوں نے کہا نظر نہیں آتا.انہوں نے بھی ٹھیک کہا.اور جنہوں نے کہا نظر آتا ہے انہوں نے بھی ٹھیک کہا.جنہوں نے کہا نظر آتا ہے انہوں نے اس شان کے لحاظ سے کہا جو بندوں سے تعلق رکھتی ہے.اور جنہوں نے کہا نظر نہیں آتا انہوں نے ان صفات کے لحاظ سے کہا جو احدیت کے گرد چکر لگاتی ہے.پس خدا تعالیٰ نظر نہیں آتا اور بے شک نظر نہیں آتا.جب تک ان صفات کو نہ دیکھیں جو بندوں سے تعلق رکھتی ہیں.اگر کوئی یہ کہتاہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ جو احدیت سے تعلق رکھتی ہیں، دیکھا ہے تو وہ غلط کہتا ہے.احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا.کیا
Page 390
آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو آپ نے جواب دیا نُوْرٌ اَنّٰی اَرَاہُ( مـسلم کتاب الایمان باب فی قولہٖ علیہ السلام انی اراہ) کہ وہ ایک نور ہے میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں.پھر جو یہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی شان میں بھی نظر نہیں آتا.وہ بھی غلط کہتاہے.دراصل دونو ں قسم کے لوگ الگ الگ نقطہ نگاہ سے بات کررہے ہوتے ہیں.الغرض خدا تعالیٰ کی احدیت دورنگ کی ہے ایک وہ جسے ہم سمجھنا چاہیںتو نفی سے ہی سمجھ سکتے ہیں.اس لئے ہمیں سمجھانے کے لئے فرمایا اَللّٰہُ الصَّمَدُ میں صمد ہوں.یعنی وہ ہستی جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہ کیا جاسکے.یہ گویا تنزّل کی احدیت کو بیان کرنا شروع کیا ہے کہ میں وہ خد اہوں جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوسکتااور جب یہ صورت ہے تو یا درکھو کہ میرے دروازہ سے بھٹکنا فائدہ مند نہیں ہو سکتا.کہیںچلے جائو کسی پیر فقیر کو حاجت روابنائو.وہ سب میرے محتاج ہیں.پس جسے چشمہ ملے وہ گلاس پر کیوں بیٹھ جائے اور میں ہی وہ چشمہ ہوں جس سے تمام لوگ اپنے اپنے کوزے اور گھڑے بھرتے ہیں.جب تم مجھ ہی سے حاصل کرتے ہو توتم کیوں مجھ سے تعلق پیدا نہ کرو اور مجھ ہی سے نہ مانگو.جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکاہے.اللہ تعالیٰ کی دوصفات ہیں.ایک احد ہونا اور دوسری واحد ہونا.اوراِن دونوں میں فرق ہے جب ہم واحد کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے ساتھ دو، تین، چار یا کم وبیش دوسرے افراد کے وجود کا بھی اقرار کرتے ہیں.انکار نہیں کرتے.گویا ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ باقی جو چیزیں ہیں اسی سے نکلی ہیں.جس طرح دوتین چار وغیرہ سب عدد ایک سے ہی نکلے ہیں.اسی طرح دنیا میں جس قدر بھی اشیاء ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ سے ہی نکلی ہیں اور ہر چیز اپنے کمال کے لئے اس کے پرتَو کی محتاج ہے.جس طرح سورج کی روشنی کے بغیر اور کہیں نور نہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر اور کوئی وجود نہیں ہوسکتا.یہ تومفہوم ہے واحد کا.اَحَدٌ کالفظ یہ مضمون بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے.یہ دو قسم کی نفی کرتا ہے.پہلی یہ کہ وہ دوسے ایک نہیں ہوا.اور دوسری یہ کہ وہ ایک سے بھی دو نہیں ہوا.واحد ایک سے دوبنتا ہے اگر پیچھے کی طرف دوہیں تو دوسے ایک ہوجاتا ہے.جہاں تک خدا تعالیٰ کی صفات کا تعلق ہے ان کے ساتھ دنیا کا اشتراک پایا جاتاہے.اس کے پرتَو کے ماتحت دوسری اشیاء میں بھی ایک حد تک وہ صفات مل سکتی ہیں گویا واحد کہنے کے ساتھ ہم اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے وجود بھی موجود ہیں.واحد کے لفظ سے ہم دوسرے کسی وجو د کی طرف جا سکتے ہیں مگر احد کے لفظ سے نہیں.اسی طرح عربی زبان میں واحد اثنان کہتے ہیں.یعنی ایک، دو، تین.احد، اثنان، نہیں کہتے.تومخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اشتراک ہے ذات میں نہیں.اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کے پرتَو سے ہمیں بھی سننے کی توفیق حاصل ہوتی ہے.کئی نادان کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہم بھی سنتے ہیں اور خدا تعالیٰ بھی سنتا ہے یہ
Page 391
شرک ہے.لیکن یہ شرک نہیں.کیونکہ ہم جو سنتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا پرتَو ہے.پس جب ہم واحد کا لفظ بولتے ہیں تو اقرار کرتے ہیں کہ دوسرے وجود بھی دنیا میں ہیں جو اس سے طاقت حاصل کر کے صفات ظاہر کرتے ہیں.ایک سے آگے دو، تین، چار، پانچ وغیرہ ہیں.اور اگر پھر واپس چلیں تو ایک پرہی پہنچ جاتے ہیں.مگر احد کا لفظ بتاتاہے کہ نہ اس ایک سے آگے دوتین چار کی طرف جاسکتے ہیں اور نہ واپس ایک کی طرف آسکتے ہیں.اور اصل بنا مخاصمت کی یہی ہے.بہت سی قومیں ہیں جو ایک سے دوتین کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر واپس ایک کی طرف لاتی ہیں.چنانچہ عیسائیوں میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں.وہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اورروح القدس مل کر ایک ہوا گویا وہ کثرت سے وحدت کی طرف لے جاتے ہیں.کہ تینوں مل کر ایک ہو گئے.سورۃ الاخلاص یہ کہتی ہے کہ واحدیت تو اقنوم ثلاثہ سے پیدا ہو سکتی ہے لیکن احدیت نہیں پیدا ہو سکتی.اور توحید کا مل کا یہی مقام ہے چونکہ یہ غلطی خصوصیت کے ساتھ آخری زمانہ میں پیدا ہونے والی تھی اس لئے قرآن کریم کے اختتام پر فرمایا قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌتو کہہ دے اللہ منفرد ہے وہ نہ تو ایک سے بیٹا اور روح القدس بن سکتا ہے اور نہ یہ تینوں واپس ایک ہوسکتے ہیں.وہ نہ تو تنوع اختیار کرسکتا ہے اور نہ اس تنوع کو مٹانے سے پھر ایک ہوتاہے.الغرض سورۃ الاخلاص اس آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ کی احدیت کو ثابت کرنے کے لئے اتاری گئی ہے.اس مختصر سی سورۃ کے ذریعہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے.وہاں شرک کا بھی کلیۃً استیصال کر دیاہے.شرک دو قسم کا ہوتاہے ایک تو یہ کہ کئی وجود خدا کی حیثیت رکھنے والے ہوں.چاہے اس سے چھوٹے ہوں یابڑے.دوسر ے یہ کہ خدا کے سوا باقی ہو تو مخلوق ہی، مگر اسے خدائی کا درجہ دیا گیا ہو.تو ایک شرک فی الذات ہے اور دوسرا شرک فی الصفات.اللہ تعالیٰ نے قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کہہ کر تما م ان لوگوں کے عقائد کی تردید کر دی جو تین خدا کہتے ہیں یا دوخدائوں کے قائل ہیں.یاخدا کا بیٹا یا بیٹیاں تجویز کرتے ہیں یا اور بتوں کو پوجتے ہیں.چنانچہ قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کے بعد اَللّٰہُ الصَّمَدُ اور پھر لَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو لوگ شرک کرتے ہیں اور دوسروں کو اس کی صفات میں شریک قرار دیتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے خواہ کتنا ہی کوئی بڑا انسان ہو.وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے نہ اس کے رتبہ کو کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک فی الفعل ہو سکتا ہے.
Page 392
اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ۰۰۳ اللہ وہ (ہستی) ہے جس کے سب محتاج ہیں(اور وہ کسی کا محتاج نہیں ).حلّ لُغات.الصَّمَدُ.الصَّمَدُ:اَلسَّیِّدُ الَّذِیْ لَا یُقْضٰی دُوْنَہٗ اَمْرٌ.وہ سردار جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہ کیا جاسکے.اَلدَّائِمُ.ہمیشہ رہنے والی ذات.اَلرَّفِیْعُ.بہت بلند ہستی.(اقرب) اَلصَّمَدُ: السَّیِّدُ الَّذِیْ یُصْمَدُ اِلَیْہِ.وہ سردار جس کی طرف حوائج اور ضروریات کے وقت قصد کیا جاتاہے.(مفردات) تفسیر.اَللّٰہُ الصَّمَدُ.صمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو خود کسی کی محتاج نہ ہو بلکہ باقی سب چیزیں اس کی محتاج ہوں.قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ میں یہ دعویٰ تھا کہ اللہ ہے اور ایک ہے اب اس دعویٰ کی دلیل اَللّٰہُ الصَّمَدُ میں دی گئی ہے.مفسرین کہتے ہیں کہ یہ محض قافیہ کی رعایت سے لفظ لایا گیا ہے.حالانکہ یہ بات درست نہیں بلکہ اس سورۃ کی ہر آیت پہلی آیت کے مضمون کی ایک مضبوط دلیل ہے چنانچہ پہلے فرمایا ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ.یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ منفرد ہے اور پھر فرمایا کہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اَللّٰہُ الصَّمَدُ دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے اور جب ساری چیزیں اس کی محتاج ہیں اور وہی ہمارے سب کا م پورے کرتاہے تو پھر کسی اور رب کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے.لیکن اگر اس کے باوجود کسی کو رب تسلیم کیاجائے تو ماننا پڑے گا کہ وہ لغو خدا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ خدا جو لغو ہے خدا نہیں ہوسکتا.جب لغو پانی، لغو ہوا اور لغو کھانا بھی بے کار ہوتا ہے تو لغو خدا کی کیا قیمت ہو سکتی ہے.پس جب ایک ہی خدا ساری چیزیں پیدا کرتا ہے اور وہی ہر چیز کی احتیاجوں کو پورا کرتا ہے توکسی اور سے ان احتیاجوں کو وابستہ کرنا لغو ہے.غرض اَللّٰہُ الصَّمَدُ میں توحید کی دلیل دی گئی ہے.کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ایسا دعویٰ ہے جس کی دلیل لوگوں کے سامنے نہیں.کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں.اس کی ذات ان مادی آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے اور نہ اس کی ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں.پس اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے اوروہ یہ کہ ہم یہ ثابت کردیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک محتاج ہے.جب یہ ثابت ہوجائے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے تو یہ بات خود بخود ثابت ہوجائے گی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں.یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو روزروشن کی طرح واضح ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنی ذات میں کامل ہو.ہر چیز اپنے وجود کے لئے دوسری اشیاء کی محتاج ہے اور بغیر ان کے قائم نہیں رہ سکتی.ELEMENTSکے باریک سے باریک ذرّات کی طرف چلے جائیں تو معلوم ہو گا کہ ہر ایک ذرّہ کا
Page 393
دوسرے ذرّ ہ پر اثر پڑ رہا ہے.کہیں نور کا اثر پڑرہا ہے کہیں ایتھر کا اثر ہورہا ہے.انسان کامل چیز سمجھی جاتی ہے لیکن یہ پانی، روٹی اور ہوا کا محتاج ہے.سورج ہے جو گیس کا محتاج ہے اپنے حجم کو قائم رکھنے کے لئے دوسرے سیاروں سے مواد لینے کا محتاج ہے اور بیسیوں اشیاء کا محتاج ہے زمین ہے تو وہ اپنے وجود کے قیام کے لئے کہیں دوسرے ستاروں کی کشش کی، کہیں کرۂ ہوا کی پھر ایتھر کے نئے مادہ کی محتاج ہے.غرض کسی بڑی سے بڑی چیز کو لے کر باریک درباریک کرتے جائو تو محتاج ہی محتاج ثابت ہوگی.پس ہر چیز جو ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے وہ اپنے وجود کے لئے دوسری اشیاء کی محتاج ہے او ریہ احتیاج بتا رہی ہے کہ دنیا اپنی ذات میں قائم نہیں.بلکہ اس کا چلانے والا کوئی اور ہے کیونکہ محتاج الی الغیر چیز اپنی خالق آپ نہیں ہوسکتی.اور نہ ہمیشہ سے ہو سکتی ہے.کوئی کہہ سکتا ہے کہ چیزوں کی احتیاج موجودہ تحقیقات کی رُو سے ہے جب تحقیقات مکمل ہو جائے گی تو شاید ثابت ہو جائے کہ بحیثیت مجموعی دنیا کسی کی محتاج نہیں.اوّل تو اس کا یہ جواب ہے کہ شاید نئی تحقیقات سے دنیا کی احتیاج اور بھی واضح ہوجائے اور اس کے خالق کا وجود اور بھی زیادہ روشن ہوجائے.پس یہ کوئی اعتراض نہیں.اس وقت تک تحقیقات کے کئی دَور بدلے ہیں.مگر یہ مسئلہ زیادہ سے زیادہ قائم ہوا ہے.کبھی اس کے خلاف کوئی بات ثابت نہیں ہوئی.پس ہر جدید تحقیق کے بعد اس اصل کا اور بھی پختہ ہو جانا ہی اس امر کا ثبوت ہے کہ آئندہ تحقیق اسے باطل نہیں کرے گی بلکہ ثابت کرے گی.لیکن اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ کوئی ایسا ذرہ معلوم ہوجائے جو اپنی ذات میں کامل ہو.توپھر بھی اس کے جوڑنے والے کی ضرورت رہے گی.لیکن درحقیقت یہ عقلاً محال ہے کہ کوئی ذرہ اپنی ذات میں کامل ہو.بغیر بالا رادہ ہستی کے اور قادر مطلق وجود کے یہ طاقت کسی میں نہیں پائی جا سکتی.پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مادہ جسے اپنی ذات میں مکمل قرار دیا جائے اس کے لئے دوسری شکل اختیار کرنا ناممکن ہے.کیونکہ تغیّر کسی دوسری شے سے ملنے سے ہوتا ہے اور ملنے کی طاقت اس میں ہوتی ہے جو نامکمل ہو.کامل شئے چونکہ تغیّر قبول نہیں کرتی وہ کسی اور چیز سے حقیقی طور پر مل بھی نہیں سکتی.اس کا ملنا ایسا ہی ہو سکتا ہے جس طرح کہ کھانڈ کے ذرّے آپس میں مل کر پھر کھانڈ کی کھانڈ ہی رہتے ہیں.پس اگر ایسا کوئی ذرّہ فی الواقع ہے تو یہ دنیا اس سے پیدا ہی نہیں ہوسکتی کیونکہ دنیا تو بے تعداد تغیّرات کا مقام ہے.غرض کائنات عالم پر غور کرنے سے صاف ثابت ہوتاہے کہ یہاں کی ہرچیز تغیّر پذیر ہے اور اپنی ہستی کے قیام کے لئے دوسروں کی محتاج.اس لئے کسی ایسی ہستی کا ماننا جو ان محتاج ہستیوں کو وجود میں لانے والی ہو اور ایک قانون کے ماتحت چلانے والی ہو ضروری ہے.بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مخفی طاقت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے.مگر سوال یہ ہے کہ وہ مخفی طاقت بالارادہ ہے یا بلا ارادہ؟
Page 394
اگر بلاارادہ ہے تووہ خود دوسری چیزوں سے پیدا ہوتی ہے.کیونکہ تمام طاقتیں دوسری چیزوں کی حرکت یا باہمی ترکیب سے پیدا ہوتی ہیں.اور اگر بالارادہ ہے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہے.ہم بھی تو ایسی ہی طاقت کو منوانا چاہتے ہیں.غرض کہ اَللّٰہُ الصَّمَدُ میں خدا تعالیٰ کے وجود کی ایک نہایت ہی عجیب دلیل دی گئی ہے.الصَّمَدُ کے دوسرے معنے اَلرَّفِیْع کے ہیں.یعنی بلند درجات والا.ان معنوں کے لحاظ سے اَللّٰہُ الصَّمَدُ کے معنے یہ ہوں گے کہ وہ ذات جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ وہ احدیت کی شان رکھتا ہے وہ رفیع الدرجات ہے اور غیر محدود ہے اور قیاسات سے بالا ہے.گویا ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم نے رفیع الدرجات خدا کی طرف پرواز کرنی ہے تو پھر جتنی بھی پرواز کریں کم ہے کیونکہ ہمارا خدا رفیع ہے اور غیر محدود ہے.اور اس تک ترقی کرنے کے ذریعے کھلے ہیں.اورخواہ کوئی کتنا ہی ترقی کرے وہ اس کے نیچے ہی رہے گا اور کوئی ایسی انتہا نہیں جہاں پر پہنچ کر ہم کہیں کہ اب سفرختم ہے.اَلصَّمَدُ کے ایک معنے تفاسیر میں غنی کے بھی کئے گئے ہیں.لیکن غنی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور یہ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم نامکمل ہے.اس کے مقابل پر صمد دوہرے معنے رکھتا ہے یعنی وہ ہستی جو خود کسی کی محتاج نہ ہو لیکن باقی سب چیزیں اس کی محتاج ہوں.پس غنی کا لفظ صمد کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا.بلکہ آدھے مفہوم کو ادا کرتا ہے.اردو میں کوئی مفرد لفظ ایسا نہیں ہے جو صمد کے پورے مفہوم پر حاوی ہو.اگر صمد کے مفہوم کو سامنے رکھیں تو اس کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں رحمان بن جاتا ہے.کیونکہ رحمان کے معنے یہ ہیں کہ وہ بغیر عمل کے بھی ربوبیت کرتا ہے جب ہم کہیں کہ ہر شے اس کی محتاج ہے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمِ مادر میں بھی بچہ اس کا محتاج ہے کیونکہ وہ وہاں بھی اس کی ربوبیت کرتا ہے.پس جب ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز اس کی محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بکری، اونٹ اور گھوڑے بھی اس کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی احتیاج پوری کرتا ہے پھر اس کے یہ معنے بھی ہیں کہ وہ گناہ گار کا بھی رحمان ہے اور اس سے کفارہ کا ردّ ہوجاتا ہے اسی نکتہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تناسخ کا مسئلہ قائم ہواہے.ان آیات میں اس کا بھی ردّ کیا گیا ہے پھرجب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا تعالیٰ کی محتاج ہے تو پھر چاند، سورج اور ستارے اور زمین کے باریک در باریک ذرّات بھی اسی کے محتاج ہیں.نام نہاد (جس کو منطق میں بسیط کہتے ہیں ) مفر دچیزیں بھی اس کی محتاج ہیں اور مرکب چیزیں بھی.پھر مادے کا بھی وہ خالق ہے.انسانوں کا بھی اور روح کا بھی.پس ثابت ہواکہ صمدیت کے اندر رحمانیت مضمر ہے.اصل بات یہی ہے کہ توحید رحمانیت کامنبع ہے کیونکہ اگر توحید نہ ہو تو رحمانیت پیدا نہیں ہوسکتی.چنانچہ اس کی
Page 395
ایک موٹی مثال یہ ہے کہ جو قومیں توحید کی قائل نہیں.وہ رحمانیت کی بھی قائل نہیں.ہندو توحید کو نہیں مانتے لہٰذا وہ رحمانیت کے بھی قائل نہیں.اور ان کا عقیدہ ہے کہ انسان کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی.اسی طرح عیسائی توحید کے قائل نہیں اور گناہوں کی معافی کے لئے کفارہ کو ضروری خیال کرتے ہیں.پس یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو قوم توحید کو نہیں مانتی وہ رحمانیت کی بھی قائل نہیں.پھر جتنی جتنی کوئی قوم رحمانیت کی قائل ہے اتنی ہی وہ توحید کی بھی قائل ہے اور جتنی کوئی قوم توحید سے دور ہے اتنی ہی وہ رحمانیت سے بھی دورہے.مثلاً اس زمانہ میں یہودی مذہب کسی قدر رحمانیت کا قائل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی قدر توحید کو بھی ماننے والا ہے.لیکن باقی مذاہب نہ رحمانیت کے قائل ہیں اور نہ توحید کے.سورۃ اخلاص کے شروع میں فرمایا قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کہہ دو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور پھر اس کے بعد اَللّٰہُ الصَّمَدُ کہہ کر فرمایا کہ اس کا فیض جاری ہے اور ہر چیز اس کی رحمانیت سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس کی محتاج ہے.گویا ان دونوں آیات کو یکے بعد دیگرے لانے سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ توحید اور رحمانیت لازم وملزوم ہیں.اور یہ کہ صمدیت کے اندر رحمانیت مضمر ہے.جو اللہ تعالیٰ کے اَحَدٌ ہونے کی دلیل ہے.صَمَد کے ایک معنے اَلدَّائِمُ کے بھی ہیں یعنی ابدی.گویا بتایاگیاہے کہ اللہ ہے اورایک ہے اور یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس سے کوئی پہلے وجود تھا اور نہ بعد میں ہوگا بلکہ وہی ہے جو اوّل بھی ہے اور آخر بھی.لَمْ يَلِدْ١ۙ۬ وَ لَمْ يُوْلَدْۙ۰۰۴ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے.تفسیر.سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت قُلْ ھُوَاللّٰہُ اَحَدٌ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اللہ ہے مگر ایک ہے اس دعویٰ کے بعد اس کی دلیل اَللّٰہُ الصَّمَدُ کہہ کر دی.اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں کامل نہیں.بلکہ وہ دوسری اشیاء کی محتاج ہے کامل ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو کسی کا محتاج نہیں.پس کائناتِ عالم کی یہ احتیاج اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ایک زبردست ثبوت ہے.اَللّٰہُ الصَّمَدُ کے بعد لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی صمدیت کی دلیل دی اور بتایا کہ احتیاج دوباتوں کے سبب سے پیدا ہوتی ہے.اوّل ابتدائی تعلقات کی وجہ سے.دوم آئندہ کے تعلقات کی وجہ سے.ابتدائی تعلقات سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کے نیست سے ہست میں آنے اور عالم وجود میں ظاہر کئے جانے کا
Page 396
کوئی سبب ہو او رجس کے پیدا ہونے اور نیست سے ہست میں آنے کا کوئی سبب ہوگا لازماً وہ وجود محتاج ہوگا.کیونکہ اگر وہ سبب نہ ہوتا تو اس کا وجود ظاہر نہ ہوسکتا.اور آئندہ کے تعلقات سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو.کیونکہ اولاد کا ہونا نہ صرف عورت کی احتیاج کو ثابت کرتا ہے بلکہ اولاد کا وجود خود اپنے نفس کے فانی ہونے کا بھی ثبوت ہوتاہے.چنانچہ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو اپنی پیدائش کی غرض کے پورا ہونے تک زندہ رہنے والی ہو اور پھر بھی اس کے ہاں اولاد ہو مثلاً سورج، چاند، پہاڑ، دریا اور زمین وغیرہ ہیں ان چیزوں کی پیدائش ایسی ہے کہ جب تک ان کی ضرورت ہے یہ قائم رہیں گی ان پر موت نہیں آتی اس لئے ان کی نسل بھی نہیں چلتی لیکن انسان اور حیوانات اور نباتات اپنی ضرورت کے ختم ہونے سے پہلے مرجاتے ہیں اور ان کی نسل چلتی ہے.پس جس کا کوئی باپ نہ ہو یا بیٹا نہ ہو لازماً اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ غیر فانی ہے اور یہ بھی کہ وہ اپنی ذات میں مکمل ہے اور اَحَدٌ ہے.غرض لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے تعلقات کی نفی کر دی اور ایک طرف تواس کی صمدیت کا ثبو ت دے دیا اور دوسری طرف اس کی احدیت کا ثبوت دے دیا.گویا یہ دوآیتیں مل کر پہلی دو آیتوں کا ثبوت ہیں.پھر لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ کہہ کر قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفتِ صمدیت کے متعلق ایک شبہ کا بھی ازالہ کر دیا.وہ شبہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ بے شک مان لیا کہ خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام سرانجام نہیں دیا جا سکتا.مگر کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کی طاقت کبھی ختم ہوجائے.ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض لوگ بڑی بڑی طاقتیں رکھتے ہیں مگر ایک زمانہ کے بعد ان کی طاقتیں سلب ہو جاتی ہیں او روہ بالکل مقہور اور ذلیل ہو جاتے ہیں.پس کیا ایسا کوئی امکان اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق تو نہیں؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے لَمْ یَلِدْ میںدیا اور بتایا کہ اگر آئندہ اس کی طاقتیں ختم ہونے والی ہوتیں تو اس کا قائم مقام کوئی وجود پیدا ہوتا.مگر اس نے کوئی بیٹا نہیں جنا.اور بیٹوں سے وہی چیزیں مستغنی ہوتی ہیں جو اپنی ضرورت کے آخر تک قائم رہتی ہیں.پس لَمْ یَلِدْ نے ثابت کردیا کہ اس کی طاقت کبھی ختم نہیںہوگی اور اس کی صمدیت ہمیشہ قائم رہے گی.اس آیت میں ایک اور بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ لَمْ یَلِدْ کے الفاظ پہلے رکھے گئے ہیں.اور لَمْ یُوْلَدْ کے بعد میں.حالانکہ لَمْ یَلِدْ ابدیت پر دلالت کرتا ہے اور لَمْ یُوْلَدْ ازلیت پر دلالت کرتاہے اور ازلیت پہلے ہوتی ہے اور ابدیت پیچھے ہوتی ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ ازلیت کا علم کسی انسان کو نہیں ہو سکتا.کیونکہ انسان دورحاضر کی پیدائش ہے.وہ ازلیت کا علم ابدیت سے ہی حاصل کرسکتا ہے.چونکہ تما م گذشتہ تاریخ عالم اس
Page 397
بات کا ایک ثبوت ہے کہ کبھی بھی دنیا خدا کی مدد سے محروم نہیں رہی.اور دوسرے یہ ثابت ہے کہ اس کاکوئی لڑکا نہیں.اس لئے معلوم ہوا کہ وہ ابدی ہے اور جب وہ ابدی ہے تو لازماً ازلی بھی ہے.کیونکہ آئندہ کی فنا سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو گذشتہ پیدائش سے بھی محفوظ ہو.وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌؒ۰۰۵ اور (اس کی صفات میں ) اس کا کوئی بھی شریکِ کار نہیں.حلّ لُغات.كُفُوًا.كُفُوًا :اَلْکُفُؤُ.اَلْمُمَاثِلُ.یعنی کفو کے معنے مثیل اور برابر کا درجہ رکھنے والے کے ہوتے ہیں.چنانچہ اہل عرب جب کہتے ہیں.ھٰذَا کُفُؤُہٗ.تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اَیْ مُـمَاثِلُہٗ.یعنی فلاں فلاں کا مماثل ہے(اقرب).مفردات اما م راغب میں ہے کہ کفو اس کو کہتے ہیں جو کسی کا ہم مرتبہ ہو.تفسیر.مفسرین کہتے ہیں کہ لَمْ یَکُنْ لَّہٗ کُفُوًا اَحَدٌ کا جملہ پہلی آیت کے مضمون کو دہرانے اور اس کی تاکید کرنے کے لئے لایا گیا ہے.لیکن یہ درست نہیں.حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی پیدا نہ ہوئی ہو اور آگے بھی اس نے کسی کو پیدا نہ کیا ہو تو یہ شبہ رہتا ہے کہ شاید ایسی ہی کوئی او رہستی بھی موجود ہو.اس شبہ کا ازالہ اس آیت میں کیا گیا ہے اور بتایاگیا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خدا کسی کا بیٹا نہیں یا خدا کا آگے کوئی بیٹا نہیں بلکہ اس کا مماثل اور مشابہ بھی کوئی نہیں.اب رہا یہ سوال کہ اس کی دلیل کیا ہے.سو اس کی دلیل قرآن شریف میں دوسری جگہ پر دی گئی ہے.اور وہ یہ ہے کہ لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (الانبیآء:۲۳) یعنی اگر دومماثل ہستیاں ہوتیں تو دنیا میں فساد پڑ جاتا کیونکہ دو مماثل ہستیاں ہونے کے یہ معنے ہوتے کہ ان مماثل ہستیوں میں سے ایک بے کارہے.کیونکہ اگر دونوں ہستیاں ایک ساکام کرسکتی ہیں تو پھر فضول طور پر دوہستیاں کیوں ہیں.پس لَفَسَدَتَا کے یہی معنے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش بےکار ہوجاتی.دوسرے یہ بتایا ہے کہ اگر مماثل ہستیاں ہوں گی تو وہ متوازی سکیمیں بھی دنیا میں چلائیں گی.لیکن اگر متوازی سکیمیں اس دنیا میں چلتیں تو دنیا کا ایک حصہ کسی اور طرف جارہا ہوتا اور دوسرا حصہ کسی اور طرف جارہا ہوتا.مگر ایسا نہیں ہے ساری دنیا میں ہمیں ایک ہی قانون چلتا ہوا نظر آرہا ہے.حتی کہ جو قانون سورج پر جاری ہے وہی زمین پر بھی جاری ہے اور وہی ماوراء ھما بھی جاری ہے.یعنی ان دونوں کرّوں سے اوپر بھی جاری ہے.پس جبکہ ایک ہی قانون دنیا میں جاری ہے.تو دو مماثل ہستیاں جو ایک سی طاقت رکھتی ہوں ان کا وجود باطل ہو جاتا ہے.
Page 398
پھر اس آیت میں ایک لطیف پیرایہ میںاس حقیقت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے مشابہ صفات انسانوں میںبھی پائی جاتی ہیں.پھر بھی خدا تعالیٰ کا کوئی ہمتا اور ہمسر نہیں.کیونکہ انسان کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں.وہ ایسے طور پر نہیں پائی جاتیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کفو ہو سکے مثلاً ظاہر ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ میںبصیر ہے اور انسان بھی اپنے دائرہ میں سمیعـ ہے.لیکن انسان کی بصارت اور سماعت اتنی ناقص اور محدود ہے کہ اسے خدا تعالیٰ کی بصارت اور سماعت کے مقابلہ میں قطعاً نہیں رکھا جا سکتا جیسے جانور بھی دیکھتا ہے اور انسان بھی دیکھتا ہے اور جانور بھی کھاتا ہے اور انسان بھی کھاتا ہے.اور جانور بھی چلتا ہے اور انسان بھی چلتاہے.لیکن پھر بھی جانور اور انسان کو کفو نہیں کہا جاتا.کیونکہ انسان اپنی آنکھوں سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لیتا.اور انسان اپنے منہ سے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لیتا.اور انسان اپنے پَیروںسے جو کام لیتا ہے وہ جانور نہیں لے سکتا.دیکھو انسان اپنی آنکھوں سے کام لے کر آئندہ کے نظریات قائم کرتاہے.لیکن جانور ایسا نہیں کرتا.انسان اپنے منہ سے کھاتا ہے لیکن اس بات کاخیال رکھتا ہے کہ میرا منہ کسی ایسی چیز کو نہ کھائے جو میری صحت کے لئے مضر ہو لیکن جانور ایسا نہیں کرتا.اسی طرح انسان اپنے پیروںسے چلتا ہے اور جانور بھی اپنے پیروں سے چلتا ہے لیکن انسان اسی پیروں کی حرکت کو جس سے وہ چلتاہے پیڈل کے استعمال میں بھی کام لے آتا ہے.جس کے مطابق اس نے سائیکل ایجاد کیا.اور بعض قسم کی کشتیاں ایجاد کیں.لیکن جانور ایسا نہیں کرتا.اس کے پیروں کی حرکت ایک محدود طور پرچلتی ہے.اس لئے وہ انسان کا کفو نہیں.اسی طرح اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی سمع اور بصر پر خدا تعالیٰ کی سمع اور بصر کو قیاس نہیں کرنا چاہیے.خدا تعالیٰ کا دیکھنا اور طرح کا ہے او رانسان کا دیکھنا اور قسم کاہے.مثلاً خدا ماوراء الوریٰ دیکھتا ہے انسان نہیں دیکھ سکتا ایک دیوار کے پیچھے جو چیز آتی ہے وہ انسان کی نظر سے اوجھل ہوجاتی ہے لیکن خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتی.اسی طرح انسان بولتا ہے تو لازماً دوسرے آدمی اس کو سن لیتے ہیں.لیکن خدا اپنے نبیوں سے بولتا ہے اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ بھی نہیں سنتے او روہ ہزارپردوں کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں ان کو بتا دیتا ہے.جس کو بعض دفعہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نہیں جانتے.پس انسان باوجود سمیع اور بصیر ہونے کے خدا کا کفو نہیں.اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے او راس شبہ کا ازالہ کردیا گیا ہے.جیسا کہ اوپر کی سطور میں بتایا جا چکا ہے یہ سورۃ آخری زمانہ میں دہریت اور عیسائیت جیسے خطرناک فتنوں کے مٹانے اور اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی احدیت کو ثابت کرنے کے لئے او رتمام قوموں کو ایک نقطۂ مرکزی پر جمع کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مختلف نام دنیا میں
Page 399
بولے جاتے رہے.کوئی اسے گاڈ GOD کہتا، اور کوئی پرمیشور، کوئی یزدان کہتا اور کوئی الوہیم.اور لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے تھے کہ فلاں ہندوئوں کا خدا ہے اور فلاں زرتشتیوں کا.فلاں یہودیوں کا خدا ہے اور فلاں عیسائیوں کا.بلکہ خود ان قوموں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتاتھا کہ تمہارا خدا جو پرمیشور یا الوہیم ہے تمہیں یوں کہتا ہے.گویا پہلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ایک قومی ہو کر رہ گیا تھا.آخر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بنی نوع انسان پر اپنا اسم ذات یعنی لفظ اللہ ظاہر کیا.اور دنیا کو بتایا کہ گاڈ اور یزدان اور الوہیم وغیرہ سب اللہ کے نام کی طرف اشارے ہیں.ورنہ اصل میںایک ہی خدا ہے جس کانام اللہ ہے.اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میںبھی اشارہ فرمایا ہے وَ لَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ (لقمان:۲۶) یعنی اگر تُو ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے.اس کے یہ معنے نہیں کہ وہ اللہ کا نام لیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ جو بھی نام لیں گے.ان کا اشارہ اللہ ہی کی طرف ہوگا.پس اصل چیز ایک ہی ہے یعنی خواہ ہندو او رعیسائی اس کا کوئی نام رکھیں.مراد درحقیقت یہی ہے کہ اللہ سب چیزوں کا خالق ہے.پس اللہ قومی نہیں بلکہ رب العالمین ہے اور دنیا کی ساری قومیں کسی نہ کسی نام سے اس کو مانتی اور تسلیم کرتی ہیں.
Page 400
سُوْرَۃُ الْفَلَقِ مَدَنِیَّۃٌ سورۃ الفلق.یہ سورۃ مدنی ہے وَھِیَ سِتُّ اٰیَاتٍ مَعَ الْبَسْمَلَۃِ اور بسم اللہ سمیت اس کی چھ آیات ہیں سورۃ الفلق مدنی سورۃ ہے حسن، عطاء، عکرمہ اور جابر کہتے ہیں کہ یہ سورۃ مکّہ میں نازل ہوئی.حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے او رقتادہؓ بھی یہی کہتے ہیں.(روح المعانی تعارف سورۃ الفلق) سورۃ الفلق کے نزول کے متعلق ایک روایت علّامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب اتقان میں لکھا ہے کہ مختار قول یہی ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے.جولوگ اس بات کے حق میں ہیں کہ یہ سورۃ مدنی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اس سورۃ اور اس کے بعد کی سورۃ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کے ساتھ ہے جس میں یہ سمجھا گیا تھا کہ یہود کی طرف سے آپ پر جادو کیا گیا ہے.اس وقت یہ دو سورتیں نازل ہوئیں اور آپ نے ان کو پڑھ کر پھونکا.مفسّرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ مدینہ میں ہوا تھا اس لئے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مدنی ہیں.بہر حال ترجیح اسی کو دی گئی ہے کہ یہ دونوں سورتیں مدنی ہیں.یہ مفسرین کا ایک استدلال ہے تاریخی شہادت نہیں.گو ہمارے پاس بھی ایسی کوئی یقینی شہادت نہیں کہ جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ یہ مکّی سورۃ ہے.مگر جو استدلال کیا گیا ہے وہ بھی بودا ہے کیونکہ خواہ یہ سورۃ مکّہ میں نازل ہوتی تب بھی تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے موقع پر اس کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک سکتے تھے.پس محض پھونکنے سے یہ سمجھنا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی یہ استدلال درست نہیں.لیکن چونکہ ان سورتوں سے قرآن کریم کو ختم کیاگیا ہے ہم اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ سورۃ یا تو مکہ اور مدینہ دونوں میں نازل ہوئی ہے اور یا پھر مدنی ہے.کیونکہ قرآ ن کریم کا اختتام مدینہ منورہ میں ہواہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اور لوگوں کا یہ سمجھنا کہ آپ پر یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا ہے یہ واقعہ جن الفاظ میں روایت کیا گیا ہے وہ الفاظ یہ ہیں :.عَنْ عَائِشَۃَ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْـھَا قَالَتْ سُـحِرَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ حَتّٰی اَنَّہٗ
Page 401
لَیُخَیَّلُ اِلَیْہِ اَنَّہٗ فَعَلَ الشَّیْءَ وَلَمْ یَکُنْ فَعَلَہٗ حَتّٰی اِذَا کَانَ ذَاتَ یَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَیْلَۃٍ دَعَا اللہَ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا قَالَ اَشْعَرْتِ یَاعَائِشَۃُ اَنَّ اللہَ تَعَالٰی قَدْ اَفْتَانِیْ فِیْـمَا اسْتَفْتَیْتُہٗ فِیْہِ قُلْتُ وَمَا ذَاکَ یَا رَسُولَ اللہِ فَقَالَ جَآءَ نِیْ رَجُلَانِ فَـجَلَسَ اَحَدُھُمَا عِنْدَ رَأْسِیْ وَالْاٰخَرُ عِنْدَ رِجْلِیْ فَقَالَ الَّذِیْ عِنْدَ رَأْسِیْ لِلَّذِیْ عِنْدَ رِجْلِیْ اَوِالَّذِیْ عِنْدَ رِجْلِیْ لِلَّذِیْ عِنْدَ رَأْسِیْ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوْبٌ قَالَ مَنْ طَبَّہَ قَالَ لَبِیْدُ بْنُ الْاَعْصَمِ قَالَ فِیْ اَیِّ شَیْ ءٍ قَالَ فِیْ مُشْطٍ وَّ مُشَاطَۃٍ وَجُفِّ طَلْعَۃٍ ذَکَرٍ قَالَ فَاَیْنَ ھُوَ قَالَ فِیْ بِئْرِذِیْ أَرْوَانَ قَالَتْ فَاَتَاھَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فِیْ اُنَاسٍ مِنْ اَصْـحَابِہٖ ثُمَّ قَالَ یَا عَائِشَۃُ وَاللہِ لَکَاَنَّ مَاءَھَا نُقَاعَۃُ الْـحِنَّآءِ وَلَکَاَنَّ نَـخْلَھَا رُؤُوْسُ الشَّیَاطِیْنِ قَالَتْ فَقُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اَفَلَا اَحْرَقْتَہٗ قَالَ لَا اَمَّا اَنَا فَقَدْ عَافَانِیْ اللّٰہُ تَعَالیٰ وَکَرِھْتُ اَنْ اُثِیْرَ عَلَی النَّاسِ شَـرًّا فَاَمَرْتُ بِـھَا فَدُفِنَتْ وَھَذَانِ الْمَلَکَانِ عَلٰی مَایَدُلُّ عَلَیْہِ رِوَایَـۃُ ابْنُ مَـرْدَوَیْـہِ مِـنْ طَــرِیْقِ عِکْرَمَۃَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ھُمَا جِبْرِیْلُ وَمِیْکَائِیْلُ عَلَیْھِمَا السَّلَامُ وَمِـنْ حَـدِیْـثِــھَـا فِی الــدَّلَائِـلِ لِلْبَیْـھَقِیْ بَعْدَ ذِکْرِ حَدِیْثِ الْمَلَکَیْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ غَدًا وَمَعَہٗ اَصْـحَابُہٗ اِلَی الْبِئْرِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَاسْتَخْرَجَ جُفَّ طَلْعَۃٍ مِنْ تَـحْتِ الرَّاعُوْثَۃِ فَاِذَا فِیْـھَا مِشْطُ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَمِنْ مُّشَا طَۃِ رَأْسِہٖ وَاِذَا تِمْثَالٌ مِنْ شَـمْعٍ تِـمْثَالُ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَاِذَا فِیْـھَا اِبَـرٌ مَغْرُوْزَۃٌ وَاِذَا وُتِرَ فِیْہِ اِحْدٰی عَشَـرَۃَ عُقْدَۃً فَاَتَاہُ جِبْرِیْلُ عَلَیْہِ السَّلَامُ بِالمُعَوِّذَتَیْنِ فَقَالَ یَا مُـحَمَّدُ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَحَلَّ عُقْدَۃً.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَحَلَّ عُقْدَۃً.حَتّٰی فَرَغَ مِنْـھَا وَحَلَّ الْعُقَدَ کُلَّھَا وَجَعَلَ لَا یَنْزِعُ اِبْرَۃً اِلَّا وَجَدَ لَھَا اَلَمًا ثُمَّ یَـجِدُ بَعْدَ ذٰلِکَ رَاحَۃً فَقِیْلَ یَا رَسُوْ لَ اللہِ لَوْ قَتَلْتَ الْیَـھُوْدِيَّ قَالَ قَدْ عَافَانِیْ اللہُ تَعَالٰی وَمَا یَرَاہُ مِنْ عَذَابِ تَعَالٰی اَشَدُّ وَفِیْ رِوَایَۃٍ اِنَّ الَّذِیْ تَوَلَّی السِّحْرَ لَبِیْدُبْنُ الْاَعْصَمِ وَبَنَاتُہٗ فَـمَرِضَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ جِبْرِیْلُ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَاَخْبَرَہٗ بِـمَوْضِعِ السِّحْرِ وَبِـمَنْ سَحَرَہٗ وَبِمَ سَـحَرَہٗ فَاَرْسَلَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَلِیًّا کَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالیٰ وَجْھَہٗ وَالزُّبَیْرَ وَعَمَّارًا فَنَزَحُوْا مَآءَ الْبِئْرِ وَھُوَ کَنُقَاعَۃِ الْحِنَّآءِ ثُمَّ رَفَعُوْا رَاعُوْثَۃَ الْبِئرِفَاَخْرَجُوْا اَسْنَانَ الْمِشْطِ وَمَعَھَا وِتْرٌ قَدْ عُقِدَ فِیْہِ اِحْدٰی عَشَـرَۃَ عُقْدَۃً مُغَرَّزَۃً بِالْاِبَرِ فَـجَاءُوْا بِـھَا النَّبِيَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَـجَعَلَ یَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَیْنِ عَلَیْـھَا فَکَانَ کُلَّمَا قَرَأَ اٰیَۃً اِنْـحَلَّتْ عُقْدَۃٌ وَوَجَدَ عَلَیہِ الصَّلٰوۃُ والسَّلَامُ خِفَّۃً حَتّٰی اِنْـحَلَّتِ الْعُقْدَۃُ الْاَخِیْرَۃُ عِنْدَ تَـمَامِ السُّوْرَتَیْنِ فَقَامَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَاَنَّـمَااُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ.اَلْـخَبَرُ
Page 402
وَالرِّوَایَۃُ الْاُوْلٰی اَصَـحُّ مِنْ ھٰذِہٖ.(روح المعانی ) چونکہ مفسّرین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا کی روایت کو ترجیح دی ہے اس لئے ہم صرف اسی روایت کا ترجمہ کرتے ہیں.’’حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کی طرف سے جادو کیا گیا اور اس کا اثر یہاں تک ہوا کہ آپ بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا.ایک دن یا ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی پھر دعا کی او رپھر دعا کی.پھر فرمایا اے عائشہ ! اللہ تعالیٰ سے جو کچھ میں نے مانگا تھا وہ اس نے مجھے دے دیا.حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے.توآپ نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پائوں کے پاس.پھر وہ شخص جو میرے سر کے پاس بیٹھاہواتھا اس نے پائوں کے پاس بیٹھنے والے کو مخاطب کر کے کہا.یا غالباً یہ فرمایا کہ پائوں کے پاس بیٹھنے والے نے سر کے پاس بیٹھنے والے کو مخاطب کر تے ہوئے کہا کہ اس شخص (یعنی محمد رسول اللہ) کو کیا تکلیف ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ جادوکیا گیا ہے.اس نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے.تو اس نے جواب دیا.لبید بن الاعصم یہودی نے.تب پہلے نے کہا کہ کس چیز میں جادو کیاگیا ہے.تو دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھی او رسر کے بالوں پر جو کھجور کے خوشہ کے اندر ہے.پہلے نے پوچھا یہ چیزیں کہاں ہیں.تودوسرے نے کہا یہ ذی اروان کے کنوئیں میں ہیں.حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہؓ سمیت اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے پھر فرمایا اے عائشہ اللہ کی قسم کنویں کا پانی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے مہندی کے نچوڑ کی طرح سرخ ہوتاہے (معلوم ہوتا ہے یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی پر جادو ٹونا کرتے تھے تو مہندی یا اسی قسم کی کوئی اور چیز پانی میں ڈال دیتے تھے.یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ جادو کے زور سے پانی کو سرخ کیا گیا ہے ) اور وہاں کی کجھوریں ایسی تھیں جیسے شیاطین یعنی سانپوں کے سر ( اس میں کجھور کے گابھوں کو سانپوں کے سروں سے تشبیہ دی گئی ہے.یعنی کجھوریں گابھوں والی تھیں) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس چیز کو جس پر جادو کیا گیا تھا جلا کیوں نہ دیا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی تو میں نے ناپسند کیا کہ کوئی ایسی بات کروں جس سے شر کھڑا ہو.(یعنی یہودیوںکو یہ شور مچانے کا موقع ملے کہ انہوں نے ہماری چیزوں کو جلا دیا ہے )اس لئے میں نے حکم دیا کہ ان اشیاء کو دفن کردیا جائے چنانچہ ان کو دبادیا گیا ہے.حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں جن دو مردوں کا ذکر
Page 403
آتاہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوفرشتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے.اگر وہ انسان ہوتے تو حضرت عائشہؓ کو بھی نظر آجاتے.یہ روایت جو حضرت عائشہؓ سے بیان کی گئی ہے اس کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعہ سے خبردی کہ یہودیوں نے آپؐپر جادو کیا ہواہے.اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح جادو کا اثر تسلیم کیا جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوبھی گیا تھا.بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس قسم کا ہو جو دوسرے سے شدید عناد رکھتا ہو تو اس کی توجہ دوسرے شخص پر مرکوز ہوجاتی ہے اور جس طرح مسمریزم کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے اسی طرح جادو کا بھی ایک اثر پڑتا ہے.گویا یہ بھی مسمریزم کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں دوسرے پر توجہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے.اسی طرح یہودیوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوشش کی اور بعض دفعہ دشمن جب خاص طور پر کسی امر کے متعلق اجتماع خیال کرتا ہے تو اس کااثر مسمریزم کے طور پر دوسرے پر بھی ہو جاتاہے.جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جادو ٹونے کی چیزیں نکال کر زمین میں دفن کردیں تو یہودیوں کو خیال ہو گیا کہ انہوں نے جو جادو کیا تھا وہ باطل ہوگیا ہے.ادھر اللہ تعالیٰ نے آپؐکو صحت عطا فرما دی.خلاصہ کلام یہ کہ یہودی یہ یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اس وجہ سے طبعی طور پر ان کی توجہ اس طرف مرکوز ہوئی کہ آپ بیمار ہوجائیں چنانچہ اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی پڑا.لیکن جب خدا تعالیٰ نے حقیقت ظاہر کردی اور آپؐنے ان کی چیزیں دفن کرا دیں تو یہودیوں کی وہ توجہ ہٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت عطا فرما دی.اس روایت سے جہاں یہودیوں کے اس عناد کا پتہ چلتا ہے جو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا.وہاں یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول تھے.کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپؐکو ان تمام باتوں کا علم دے دیا گیا جو یہودی آپؐکے خلاف کررہے تھے.پس آپؐکو غیب کی باتوں کا معلوم ہوجانا اور یہودیوں کا اپنے مقصد میں ناکام رہنا آپؐکے سچا رسول ہونے کی واضح اوربیّن دلیل ہے.فضائل مسلم، ترمذی اور نسائی میں روایت آتی ہے قَالَ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّیْلَۃَ اٰیَاتٌ لَمْ اَرَ مِثْلَھُنَّ قَطُّ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (روح المعانی سورۃ الفلق) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں تو حضورنے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی بے مثل آیات اتاری گئی ہیں کہ ان جیسی پہلے نازل نہیں ہوئیں اور پھر اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھی.
Page 404
یہ سورتیں چونکہ ایک طرف قرآن کریم کا خلاصہ ہیں اور دوسری طرف ان میں مضامین کی کثرت ہے اور بعض آئندہ زمانہ کے متعلق پیشگوئیاں بھی ہیں.اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ سورتیں بے مثل ہیں یہ ان کے فضائل اور کثرت مضامین کی طرف اشارہ ہے.بخاری، ابو دائود، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا سے روایت کی ہے.اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ اِذَآ اٰویٰ اِلیٰ فِرَاشِہٖ کُلَّ لَیْلَۃٍ جَمَعَ کَفَّیْہِ ثُمَّ نَفَثَ فِیْـھِمَا فَقَرَأَ فِیْـھِمَا قُلْ ھُوَاللّٰہُ اَحَدٌ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ یَـمْسَحُ بِـھِمَا مَااسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِہٖ.یَبْدَأُ بِـھِمَا عَلیٰ رَأْسِہٖ وَوَجْھِہٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِہٖ.یَفْعَلُ ذٰلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.وَجَآءَ فِی الْـحَدِیْثِ اَنَّ مَنْ قَرَأَھُمَا مَعَ سُوْرَۃِ الْاِخْلَاصِ ثَلَاثًا حِیْنَ یُـمْسِیْ وَثَلَاثَ حِیْنَ یُصْبِحُ کَفَتْہُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ.(روح المعانی مقدمۃ سورۃ الفلق) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر میں آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے اور ہتھیلیوں میں پھونکتے اور سر سے لے کر پائوں تک سارے جسم پر مَل لیتے اور یہ فعل تین بار کرتے.نیز حدیث میں یہ بھی آتاہے کہ جو شخص ان دونوں سورتوں کو سورۃ الاخلاص کے ساتھ ملا کر صبح وشام پڑھے گا اس کے لئے یہ کافی ہوجائیں گی اور اس کی ضرورت پوری ہو گی اور دکھ درد سے محفوظ رہے گا.اس سے مراد یہ ہے کہ قرآنی تعلیم انسان کو دکھوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص صبح و شام معوّذتین پڑھے گا لازماً قرآنی تعلیم خلاصتہً صبح وشام اس کے سامنے آتی رہے گی اور جس کے سامنے صبح وشام قرآنی تعلیم آتی رہے گی اسے عمل کا بھی خیال آئے گا.اور اس طرح وہ دکھوں سے بھی محفوظ رہے گا.اسی طرح ابن مردویہ نے عقبہ بن عامر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِقْرَأُوْا بِالْمُعَوِّذَاتِ فِیْ دُبُرِ کُلِّ صَلوٰۃٍ.(درمنثور سورۃ الفلق ) یعنی اے لوگو! ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھا کرو.اسی طرح سے ابن مردویہ نے حضرت امّ سلمہ ؓ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِنْ اَحَبِّ السُّوَرِ اِلَی اللّٰہِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ دو سورتیں ہیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس.پھر یہ روایت بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص اور معوذتین کو ملاکر وتر کی آخری رکعت میں پڑھا کرتے تھے.(درمنثورسورۃ الفلق)
Page 405
یہ سب روایات ان سورتوں کے فضائل کو ظاہر کرتی ہیں اور ہمیں اس طرف راہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں ہروقت اللہ تعالیٰ پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اس کی پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے.وتر کی آخری رکعت چونکہ دن کی نمازوں کے خاتمہ پرہوتی ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ دونوں سورتیں ملا کر پڑھتے تھے.اورآپؐکا یہ فرمانا کہ جو شخص صبح و شام ان سورتوں کو پڑھے گا وہ آفات سے محفوظ ہو جائے گا.اس کے معنے یہ ہیں کہ انسان کو اپنی ابتدا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہیے اور اپنی انتہا بھی قرآنی تعلیم پر رکھنی چاہیے.بعض لوگوں نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے متعلق یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ سورتیں دراصل قرآن کریم کا حصہ نہیں.اگرچہ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ساتھ لکھوایا ہے اور قرآن کریم کے خاتمہ پر انہیں پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کا حکم دیتے تھے.مگر باوجود اس کے ان کا خیال ہے یہ سورتیں قرآن کریم کاحصہ نہیں.چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابہ میں سے تھے ان کی یہی رائے ہے.لیکن اس کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں.واقعات کے متعلق دلیل صرف وہی شہادت ہوسکتی ہے جو یا تو نظری ہو یا سماعی.یعنی یاتو اس کی شہادت جس نے خود واقعہ دیکھا ہے یا پھر اگر کسی اور کی طرف اس فیصلہ کو منسوب کرے تو اس کے الفاظ بیان کرے.لیکن حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا یہ بیان نہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں سورتوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ استعاذہ کیاکریں.اور چونکہ یہ دونوں سورتیں استعاذہ ہیں.اس لئے معلوم ہوا کہ قرآن ختم ہو گیا.ظاہر ہے کہ یہ محض ان کا قیاس ہے اس کے مقابل دوسرے مقتدر صحابہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورتیں انہیں قرآن کے حصہ کے طور پر لکھوائیں.اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قیاس درآنحالیکہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ قرآن کریم کے ساتھ لکھی اور پڑھی جاتی تھیں کوئی وقعت نہیں رکھتا.پس یہ سورتیں یقیناً قرآن کریم کا حصہ ہیں اور قرآن کریم کے خاتمہ کے لئے خدا تعالیٰ نے ان کو چنا ہے.تعلق جیسا کہ قبل ازیں سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آخری تین سورتیں مجموعی لحاظ سے قرآن مجید کا اسی طرح خلاصہ ہیں جس طرح کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے.چنانچہ سورۃ الاخلاص میں وہی مضمون بیان ہوا ہے جو سورۃ فاتحہ کی آیات اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ.اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ میں بیان ہوا ہے.سورۃ الاخلاص کے بعد سورۃ الفلق ہے.اس میں سورۃ فاتحہ کی آیات رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور
Page 406
غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ کا مضمون بیان کیا گیاہے.کیونکہ سورۃ الفلق کی ابتدا میں قُلْ اَعُوْذُ کے الفاظ ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس جگہ کسی شرّ کا ذکر ہے جس سے پناہ مانگنے کے لئے کہا گیا ہے.چنانچہ فرمایا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.یعنی میں اس خدا سے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے دنیا کی ہر شے کی برائی سے پناہ مانگتاہوں.پس رَبِّ الْفَلَقِ میں خدا تعالیٰ کے رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ہونے کا ذکر آگیا.اور مَا خَلَقَ کے شر سے پناہ مانگنے میں غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْھِمْ والی دعا آگئی.مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَمیں جس کے معنے ہیں کہ جب تاریکی سب طرف چھاجاتی ہے یہ بتایا کہ بعض اوقات ربوبیتِ عالمین کی صفت دنیاسے مخفی ہو جاتی ہے.میں اس سے پناہ مانگتاہوں اور مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ میں جس کے معنے ہیں ہر حسد کرنے والے کے حسد سے میں محفوظ رہوں.ربوبیت کے مخصوص اخفاء کا ذکر کیا.کیونکہ حسد تب ہوتا ہے جب کچھ لوگوں پر انعام ہو رہا ہو اور کچھ پر سزا نازل ہورہی ہو.پس سورۃ الفلق میں دعا سکھائی کہ خدا یا جب دنیا میں تیرا عام غضب نازل ہورہا ہو اس وقت بھی ہم کو بچا اور جب خاص غضب نازل ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم کو بچا تاکہ نہ ہم حاسد بنیں اور نہ محسود ناکام.کیونکہ بعض محسود بھی دوسروں کے حسد کے نتیجہ میں ناکام ہوجاتے ہیں.الغرض سورۃ فاتحہ کے مضمون کا کچھ حصہ سورۃ الاخلاص میں آگیا اور کچھ سورۃ الفلق میں اور باقی حصہ سورۃ الناس میں بیان ہواہے اور اس طرح وہ سارا مضمون جو سورۃ فاتحہ میں بیان ہواہے.آخری تین سورتوں میں دہرا دیا گیا ہے.اس سورۃ کا سورۃ اخلاص سے یہ تعلق بھی ہے کہ سورۃ اخلاص میں توحید کامل کا سبق سکھایا گیا ہے او ربتایا گیا ہے کہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں.پھر اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ہر مسلمان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی توحید کے جھنڈے کو بلند رکھے.اور کسی جابر، ظالم اور دشمنِ اسلام سے ڈرے نہیں.اور یہ یقین رکھے کہ صرف ایک خدا تعالیٰ کی ہستی ہی ہے جس کے اشارہ پر ساری کائنات حرکت کرتی ہے اور وہ خدا ہر خیر کے دینے او رہر شر سے محفوظ رکھنے پر قادر ہے.پس اس کی توحید کا اعلان کرنے کے لئے مخلوق میں سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں.کیونکہ جب کوئی شخص توحید کی اشاعت کے لئے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرے گا اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہ کرسکے گا.سورۃ الفلق کا تعلق سورۃ نصر سے بھی ہے.سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ اسلام بڑھے گا، پھولے گا اور پھلے گا اور کوئی اس کی ترقی کو روک نہیں سکتا.سورۃ الفلق میں یہ بتایا کہ اے
Page 407
مسلمانو! جب تمہیں خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں کے مطابق غلبہ مل جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے حضور جُھک جانا اور دعا کرنا کہ تمہارے اندر کوئی ضعف پیدانہ ہو اور تمہارا سورج کبھی ڈوبنے نہ پائے بلکہ نصف النہار پر چمکتا رہے.اور کسی قسم کا شر پیدا نہ ہواور نہ توتمہارا اندرونی نظام درہم برہم ہو کر تمہارا شیرازہ بکھر ے اور نہ کوئی بیرونی حاسد کھڑا ہوجائے اور تمہاری حکومت کو تباہ کردے.بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۰۰۱ (میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے انتہا کرم کرنے والا (اور ) بار بار رحم کرنے والا ہے ( اس سورۃ کو شروع کرتاہوں) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ۰۰۲ (ہم ہر زمانہ کے مسلمان سے کہتے ہیںکہ) تُو (دوسرے لوگوں سے ) کہتا چلا جا کہ میں مخلوقات کے رب سے (اس کی) پناہ طلب کرتا ہوں.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ۰۰۳ اس کی ہر مخلوق کی (ظاہری اور باطنی ) برائی سے (بچنے کے لئے ) حلّ لُغات.اَعُوْذُ.عَاذَ سے مضارع متکلم کا صیغہ ہے.اور عَاذَ بِہٖ مِنْ کَذَا کے معنے ہیں.لَـجَأَ اِلَیْہِ وَاعْتَصَمَ.کسی کی پناہ اور حفاظت میں آکر بچائوچاہا.چنانچہ جب اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ کہتے ہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں.اَلْتَجِیُٔ اِلَی اللہِ وَاعْتَصِمُ مِنَ الشَّیْطَانِ.کہ میں اللہ کی پناہ میں آکر شیطان کے حملوں سے بچتاہوں.اور جب عَاذَ بِالشَّیْءِ کہیں تو معنے ہوں گے لَزِمَہٗ اس کے ساتھ چمٹ گیا.نیز جب عَاذَتْ بِوَلَدِ ھَا کافقرہ بولیں تو معنے ہوتے ہیں قَامَتْ مَعَہٗ.یعنی فلاں عورت اپنے بچہ کے ساتھ کھڑی ہوگئی.(اقرب) پس اَعُوْذُ کے معنے ہوں گے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں.(۲) میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتاہوں.اَلْفَلَق کے معنے ہیں.اَلصُّبْحُ.صبح.اَلْـخَلْقُ کُلُّہٗ.ساری مخلوقات.جَھَنَّمُ.جہنم.اَلْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْاَرْضِ بَیْنَ رَبْوَتَیْنِ.دو چوٹیوں کے درمیان میدانی زمین.مَقْطَرَۃُ السُّجَّانِ.وہ لکڑی جس میں اتنے چوڑے سوراخ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کی پنڈلیاں آجائیں.اس میں مجرموں کو قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے.اور
Page 408
ایک کیلا گاڑ کے سوراخ کو اس طرح تنگ کردیا جاتا کہ کوئی پائوں نہ نکال سکے.مَایَبْقٰی مِنَ اللَّبَنِ فِیْ اَسْفَلِ الْقَدَحِ.دودھ کا وہ حصہ جو آخر میں پیالہ میں رہ جاتا ہے.اور فلق اس دودھ کو بھی کہتے ہیں جو کھٹا ہو کر پھٹ جاتا ہے.وَالشَّقُّ فِی الْـجَبَلِ.اور پہاڑ میں جو شگا ف ہوتا ہے اس کو بھی فلق کہتے ہیں.(اقرب) مفردات میں ہے.اَلفَلْقُ : شَقُّ الشَّیْءِ وَاِبَانَۃُ بَعْضِہٖ عَنْ بَعْضٍ.کہ فلق کے معنے ہیں کسی چیز کا پھاڑنا اور اس کے بعض حصوں کو دوسروں سے جد اکردینا.وَقَوْلُہٗ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اَیْ اَلصُّبْحِ وَقِیْلَ الْاَنْـھَارِ الْمَذْکُوْرَۃِ فِیْ قَوْلِہٖ وَجَعَلَ خِلَالَھَا اَنْـھَارًا.اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں فلق سے مراد صبح ہے (درحقیقت صبح کو فلق اس لئے کہتے ہیں کہ پوپھٹتی ہے اور اس میں سے سفیدی نمودار ہو کر فضا ء کو دوحصوں میں تقسیم کر دیتی ہے) نیز بعض لوگوں نے فلق کے معنے نہروں کے بھی کئے ہیں اور یہ معنے اس وجہ سے ہیں کہ نہروں کا پانی زمین کو پھاڑتا ہے.(مفردات) پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے معنے ہوں گے.۱.میں اس خدا کی پناہ چاہتاہوں جو اندھیرے کے بعد روشنی پیدا کرتا ہے.۲.میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے.یا جس نے جہنم کو پیدا کیا ہے.یا جس نے دوگھاٹیوں کے درمیان ایک عمدہ میدان بنایا ہے (یعنی اسلام جو افراط و تفریط کے درمیان ہے ) ۳.یا میں اس خدا کی پناہ میں آتا ہوں جس کا اقتدار قید خانوں پر بھی ہے.۴.اس خدا کی پناہ چاہتاہوں جو نہروں کا رب ہے.۵.اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے قبضے میں پیالے کا بچاہوا دودھ ہے.تفسیر.سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوّذتان کہتے ہیں.یعنی وہ سورتیں جن کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے اور ان کا یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ان دونوں کے ابتدا میں قُلْ اَعُوْذُ کے الفاظ رکھے گئے ہیں یعنی ہر پڑھنے والے کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہ اعلان کرے کہ میں ہر قسم کے شر سے بچنے کے لئے رب الفلق اور ربّ الناس کی پناہ میں آتا ہوں.قومی لحاظ سے اور فردی لحاظ سے بھی.یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰہِ.(النحل:۹۹) یعنی اے قرآن کریم کے ماننے والے جب تُو قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کر لیا کر.پس قرآن کریم کے شروع کرتے وقت اَعُوْذُ پڑھنے کا حکم تو دیا لیکن قرآن کریم کے شروع میں اَعُوْذُ نازل نہیں کیا.
Page 409
چنانچہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہے یہ نہیں کہ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ سے شروع ہو.الغرض قرآن کریم کو شروع کرتے وقت حکم تو دیا کہ اَعُوْذُ پڑھا کرو لیکن اَعُوْذُ اتارا نہیں.اور قرآن کریم کے خاتمہ کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ جب تم قرآن کریم ختم کر لیا کرو تو اَعُوْذُ پڑھا کرو.لیکن اس کے خاتمہ پر اپنی طرف سے وحی کی صورت میں اَعُوْذُ نازل کردیا ہے اور اس کے لئے دوسورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی آخر میں رکھ دی ہیں.جو لازماً قرآن کریم پڑھنے والے کو پڑھنی پڑتی ہیں.سویاد رکھنا چاہیے کہ اس طریق کے اختیار کرنے میں کئی ایک حکمتیں ہیں :.۱.جب انسان کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تومحض ارادہ ہی کے ساتھ خدا تعالیٰ کے کامل فضلوں کا وارث نہیں ہوجاتا.ارادہ کے ساتھ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے صحیح تعلیم مل جاتی ہے.یعنی اس کے ارادہ میں مدد دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کریم کے ابتداء میں اَعُوْذُ پڑھنے کے متعلق فرمایا تو وحی کے ذریعہ اَعُوْذُ کو اتارا نہیں بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اَعُوْذُ پڑھ لیا کرو.گویا ارادہ کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بتادیا.لیکن جب قرآن کریم پڑھ لیا اور عمل کرلیا تو آخر میں اَعُوْذُ والی سورتیں رکھ دیں.یعنی انسان کے اختیا رکے بغیر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے اَعُوْذُ پڑھوا دیا.پس معلوم ہوا کہ جب انسان نے ارادہ کیا تو ارادہ ہی کی امداد دی گئی.اور جب اس نے عمل کر لیا تو اس کو عمل کر کے امداد دی گئی.۲.جب بھی کوئی مسلمان قرآن کریم کو پڑھے گا خواہ ابتدا سے پڑھے یا درمیان سے یاآخر سے.تو اس وقت تک وہ قرآنی احکام کی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہوگا.کیونکہ اس نے قرآن کریم کا ابھی مطالعہ نہیں کیا.مگر جس وقت پڑھنے والا سارا قرآن کریم شروع سے آخر تک ختم کر لیتا ہے تو ایمان کی باریکیوں سے بھی واقف ہوجاتا ہے اور اس کے سامنے اعمال کی تفصیلات بھی آجاتی ہیں اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے کون کون سے اعمال بجالانے چاہئیں اور کن اعما ل کے کرنے سے مجتنب رہنا چاہیے اور پھر اسے یہ بھی علم ہوجاتا ہے کہ ٹھوکروں کی کیا کیا نوعیتیں ہوتی ہیں.گویا قرآن کریم پڑھ لینے کے بعد انسان کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور گھبراتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کروں.پس ان دونوں حالتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اَعُوْذُ سکھایا ہے.قرآن کریم کی ابتدا کرتے وقت صرف اتنا ہی حکم دیا کہ اَعُوْذُ پڑھ لیا کرو.اور اس اَعُوْذُ کے جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں.گویا قرآن کریم کے پڑھنے والے کی ذہنی کیفیت کے مطابق ہیں.اور قرآن کریم کے آخر میں جو اَعُوْذُ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہ بہت زیادہ وسیع
Page 410
مطالب پر حاوی ہے اور اس میں مضرات سے بچنے کے لئے کامل دعا سکھلائی گئی ہے.اور یہ اس شخص کی ذہنی کیفیت کے مطابق ہے جو سارے قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہے.اور ہر اونچ نیچ کا اسے علم ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیز سے بچنا چاہیے اور فلاں فلاں قسم کی چیز کا طالب ہونا چاہیے.پس ہر دو اَعُوْذُ خاص حکمتوں پر مشتمل ہیں.قرآن کریم کے شروع اور آخر میں اَعُوْذُ پڑھنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص مکان بناتے وقت نیک لوگوں کے ہاتھوں سے بنیاد رکھوائے اور عمارت کی تکمیل پر پھر دعا کرائے.یہی حال نیکی کاہے جب کوئی انسان نیکی کی عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ پہلی اینٹ خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے رکھوائے.اسی طرح ضروری ہے کہ جب وہ نیکی کی تعمیر پایۂ تکمیل کو پہنچ جائے تو اس وقت بھی خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے آخری اینٹ رکھائے.پس جو اَعُوْذُ ہم قرآن کریم کے ابتدا میں پڑھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ سے اپنی نیکی کی بنیاد رکھواتے ہیں اور جب آخر میں اَعُوْذُ پڑھتے ہیں تو گویا خدا تعالیٰ کے ہاتھوں اس تقویٰ کے مکان کا افتتاح کراتے ہیں.جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں ایمان کی عمارت مکمل نہیں ہوسکتی.یہ ایک گُر ہے جو ہمیں اَعُوْذُ پڑھنے کے حکم میں بتایا گیا ہے.۳.پھر قرآن مجید کے ابتدا میں اَعُوْذُ پڑھنے کا حکم دینے اور آخر میں اَعُوْذُ نازل کرنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیوی امور کا تو کیا ذکر ہے دینی امور کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ سے ہونی چاہیے اور ان امور کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ پر ہونی چاہیے کیونکہ کوئی شخص کتناہی دینی معاملات میں دسترس رکھتا ہو اور کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا عرفان اسے حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی حفاظت سے مستغنی نہیں ہوسکتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان جو نہ صرف تمام انسانوں بلکہ تمام نبیوں کا سردار تھا اور جو مخلوق کے پیدا ہونے کا اصل موجب تھا.یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس امر کو مدّ ِنظر رکھ کر پیدا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس سے ظاہر ہونے والا ہے جس کا ذکر ایک حدیث قدسی میں اس طرح آتا ہے کہ لَوْ لَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ.یعنی اے محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تیرا وجود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان اور مخلوق کو پیدا نہ کرتا.اتنے بڑے وجود کے متعلق بھی احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنی اتنی دیر خدا تعالیٰ کے حضورکھڑے رہتے کہ آپ کے پائوں سوج جاتے.حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ خدا تعالیٰ نے معاف کردئیے ہیں تو آپ کو تہجّد میں اس قدر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپؐنے فرمایا اے عائشہؓ کیا میں عبد شکور نہ بنوں(بخاری کتاب التھجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل).یعنی جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر اس قدر فضل
Page 411
کیا ہے تو میری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے اور میرے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں.اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی.نجات کا ذکر تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا.یا رسول اللہ ہمیں تو اپنی نجات کے لئے اعمال کی ضرورت ہے لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے نجات مقدر ہے تو آپ کو اعمال کی کیا ضرورت ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح نہیں.میری نجات بھی اس کے فضل سے ہی وابستہ ہے.تو انسان کتنا ہی اعمال صالحہ میں ترقی کرے اور کتنے بڑے بلند مدارجِ روحانیہ پر پہنچ جائے پھر بھی ایسے پہلو باقی رہ جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت سے باہر نہیں نکل سکتا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے نجات حاصل کروں گا تو اور کون ہے جویہ دعویٰ کرسکے کہ میں اتنابڑا ہو گیا ہوں کہ اب میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے مستغنی ہو گیا ہوں اور مجھے اس کے فضل کی ضرور ت نہیں رہی.بلکہ اپنے زور سے ترقی حاصل کر لوں گا مگر باوجود اس کے کہ مسلمانوں کویہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھکے رہیں اور اس سے اس کی اعانت طلب کرتے رہیں.اگر وہ چند دن بھی نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کبر اور خود پسندی میں مبتلا ہوجاتے ہیں.تھوڑے دن نمازیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پر احسان جتانے لگ جائیں گے.چند روزے رکھیں گے تو سمجھ لیں گے کہ اب خدا تعالیٰ پر احسان ہو گیا اور اب اس کا فرض ہوگیا ہے کہ وہ ان کی خواہش پوری کرے.چند ہ دیا تو اس وہم میں مبتلا ہونے لگیں گے کہ اب خدا تعالیٰ پر ان کاحق قائم ہوگیا ہے اور اگر وہ کوئی امتیازی سلوک ان سے نہیں کرتا تو نعوذ باللہ مجرم ہے.یہی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ کردیتی ہیں اور جب کسی کے اندر یہ روح پیداہوجائے تو چاہے وہ ترقی کے تمام مدارج طے کر چکا ہو اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں.اور وہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے.پس انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے تا وہ کسی موقعہ پر بھی کبر میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کے انعامات سے محروم نہ ہو جائے.کبر ابتدا میں بھی انسان کو نیکی سے محروم رکھتا ہے یعنی جب اس کے سامنے کوئی بات پیش کی جائے تو وہ اسے سن نہیں سکتااور کبر انتہا میں بھی انسان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے کیونکہ انسان یہ سمجھنے لگتاہے کہ اب وہ ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں.ہندوستان کا ایک مشہور بادشاہ ہمایوں گذراہے جب اس نے بنگال میں افغانوں کے سوری خاندان کو شکست دی.تو اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا.صوبہ بہار میںسے وہ گذر رہا تھا کہ ایک دریا کے کنارے جب اس نے اپنے لشکر کو دور دور تک پھیلا ہوا دیکھا تو اس کے منہ سے یہ فقرہ نکل گیا کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر خدا بھی
Page 412
اسے تباہ کرنا چاہے تو اسے کچھ دیر لگے.اس وقت پٹھانوں کا لشکر جو اس سے شکست کھا چکا تھا آہستہ آہستہ اس کے پیچھے آرہاتھا.مگر بدلہ لینے کے لئے نہیں کیونکہ بدلہ لینے کی اس میں ہمت نہ تھی.بلکہ اس لئے کہ اگر ہمایوں کی فوج کا اِکادُکا سپاہی مل جائے تو اسے مار دیں جیسے کہ گوریلا وار فیئر ہوتی ہے.گوریلا دراصل ایک بندر ہے جو چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے.اسی مناسبت سے اب یہ نام اس لڑائی کو دے دیا گیا ہے جس میں چھپ کر دشمن پر حملہ کیا جائے.وہ بھی اسی طرح پیچھے پیچھے چھپ کر آرہے تھے.مگر چونکہ ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا اس لئے وہ متفقہ حملہ نہیں کرسکتے تھے.جوںہی بادشاہ کے منہ سے یہ فقرہ نکلا، ایک افغانی حکمران شیر شاہ سوری جس کو ہمایوں قید کر کے ساتھ لے جا رہا تھا اس نے یہ فقرہ سن لیا.اس کو اس قدر غیرت آئی کہ اس نے زور سے جھٹکا لگایا تو وہ رسّہ جس سے وہ بندھا ہوا تھا ٹوٹ گیا.اوروہ بھاگ کر اپنے افغان لشکر سے مل گیا.چونکہ انہیں ایک لیڈر کی ضرورت تھی اس لئے جب یہ پہنچ گیا تو انہوں نے باہمی مشورہ کے بعد یک دم ہمایوں کی فوج پر شب خون مارا.جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لشکر اس طرح بکھرکر بھاگا کہ بادشاہ کو اپنی جان بچانی مشکل ہوگئی اور جیسا کہ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں ہمایوں جان بچانے کے لئے گھوڑے پر سوار ہو کر دریا میں کود پڑا.مگر جب گھوڑا منجدہار میں پہنچا تو تھک کر ڈوب گیا.اب ہمایوں بھی ڈوبنے لگا اس وقت ایک سقّہ نے آدھے دن کی بادشاہت کے وعدہ پر اس کی جان بچائی.اس کے بعد ہندوستان میں اس کے پائوں نہیں ٹکے بلکہ بھاگ کر ایران چلا گیا(تاریخ ہندوستان ہمایوں اور شیر شاہ سوری).تو دنیوی لحاظ سے ترقی کرو یا دینی لحاظ سے جہاں کبر آیا وہاں انسان تباہ ہوگیا.اس لئے قرآن کریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اَعُوْذُ رکھا ہے اور اس طرح یہ نصیحت کی ہے کہ دیکھو تم نے قرآن کریم کو پڑھا اس پر غور کیا اس کے مطالب کو سمجھا اور روحانیت میں ترقی حاصل کی.لیکن یادرکھو جہاں تم نے یہ سمجھا کہ اب اس کے بعد تمہیں دوسروں پر کوئی فوقیت حاصل ہوگئی ہے.اور تم کبر میں مبتلا ہوگئے وہی تمہاری تباہی کا دن ہوگا.اس لئے جب بھی تم کوئی دینی یا دنیوی کام کرو خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھو اور جب اس کا م کو ختم کر لو تب بھی خدا تعالیٰ پر نظر رکھو.اس میں یہ پیشگوئی بھی معلو م ہوتی ہے کہ مسلما ن آخری دنوں میں اپنی فتوحات پر جو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی متکبر ہو جائیں گے اور اس کے نتیجہ میں پھر طرح طرح کی تباہیاں ان پر نازل ہونی شروع ہو جائیں گی پس ان کو چاہیے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے رہا کریں.تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو تکبّر سے بھی بچائے اور دلی وساوس سے بھی بچائے تاکہ وہ دشمن کے حملہ سے محفوظ ہوجائیں.ایک لطیف بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے یہ ہے کہ اَعُوْذُ کے لفظ سے پہلے قُلْ کا لفظ لایاگیا ہے.بعض لوگ غور
Page 413
کرنے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں قُلْ لانے کا کیا مطلب ہے یعنی ان کے نزدیک یہاں صرف اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہنا چاہیے تھا اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ پڑھنے والا جب قُلْ کہتا ہے تو اس کے دل میں ان الفاظ سے وہ جوش پیدا نہیں ہوسکتا جو صرف اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہنے سے پیدا ہوسکتا ہے.حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم ؓ جب نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے اور یہ سورتیں پڑھتے تو اسی وجہ سے ان کا طریق یہ تھا کہ وہ کہتے قُلْ.اور پھر کچھ وقفہ کے بعد یہ الفاظ کہتے اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ تو بہت لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ قُلْ نے اس جوش کو دبادیا ہے جو بغیر قُلْ کے پیداہوسکتا ہے.حالانکہ قُلْ کہہ کر اس جوش کو زیادہ کیا گیا ہے نہ کہ کم.قُلْکے بعد اَعُوْذُ لانے کا یہ مطلب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حکم کے مخاطب ہیں اور اَعُوْذُ کہنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اوّل المخاطبین ہے.اگر قُلْ کے بغیر اَعُوْذُ ہوتاتو اَعُوْذُ کہنے والی صرف ہماری ذات ہوتی اور اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ کر ہر انسان اپنی ذات مراد لیتا تو بعض لوگ جیسا کہ پنجابی میں مشہور ہے کہہ دیتے ہماتڑاں دا کی ہے.یعنی ہمارا اَعُوْذُ کہنا کیا حقیقت رکھتا ہے لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ تم لوگوں کو کہہ دو کہ میں جس مقامِ ترقی پر پہنچ چکاہوں اس کے باوجود میں بھی ربّ الفلق کی پناہ مانگتا ہوں.تو اُمّتِ مسلمہ کے افراد اَعُوْذُ کی اہمیت کو زیادہ عمدگی سے سمجھ سکتے تھے.عام حالات میں انسان خیال کرسکتا ہے کہ اَعُوْذُ ادنیٰ درجہ کے آدمیوں کے لئے ہے.لیکن قُلْ کہہ کر بتادیا کہ ہمارے اس حکم کے پہلے مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اَعُوْذُ سے مستغنی نہیں بلک عمداً اَعُوْذُ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھک رہاہوں.پس قُلْ کہہ کر جوش کو کم نہیں کیاگیا بلکہ اس عظیم الشان انسان کے منہ سے اَعُوْذُ کہلوا کر جو کمالاتِ روحانیہ کا نقطۂ مرکزی ہے اس کی اہمیت کو زیادہ کیا گیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا نبی بھی اَعُوْذُ کا محتاج ہے تو تم کیوں نہیں.یہاں پر یہ سوال پیداہو سکتا ہے کہ اَعُوْذُ کا مفہوم یہ ہے کہ یاالٰہی میری کمزوریوں کی وجہ سے مجھ پر شیطان کا تسلّط ہو رہا ہے اس لئے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس مفہوم کے اعتبار سے استغفار اور اَعُوْذُ ہم معنی بن جاتے ہیں.گویا اَعُوْذُ پڑھنے والا اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے پردہ پوشی چاہتاہے.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہوگیا ہے(مسلم کتاب صفۃ القیامۃ باب تحریش الشیطان).پس آپ کے اَعُوْذُ پڑھنے کا کیا مطلب؟ اس سوال کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک ایک عام انسان تو اس لئے اَعُوْذُ پڑھتا ہے کہ وہ شیطان
Page 414
سے پناہ میں رہے اور جب وہ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ کہتا ہے تو وہ اپنے گناہ گار ہونے کا بھی اعتراف کرلیتا ہے.لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اَعُوْذُ پڑھناان معنی میں نہیں ہوسکتا کیونکہ آپ معصوم ہیں اس لئے قرآن کریم میں ان سورتوں کو قُلْ کے ساتھ شروع کیا گیا اور اس طرف اشارہ کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کو دیکھ کر اَعُوْذُ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر نے کے لئے پڑھتے تھے تا کہ آئندہ آپ کے اور آپ کی جماعت کے خلاف شیطان کوئی کارروائی نہ کر سکے.نبی کو اپنے ماننے والوںکا اسی طرح فکر ہوتا ہے جس طرح گلہ بان کو اپنی بھیڑوں کا.بعض اوقات گلہ بان اپنی جان کی حفاظت کا خیال نہیں رکھتا اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتا ہے مگر بھیڑوں کے بچانے کی کوشش کرتا ہے.یہی حالت نبی کی ہوتی ہے وہ اَعُوْذُ اس لئے پڑھتا ہے کہ جو بھیڑیں اس کے سپرد کی گئی ہیں وہ شیطان کے حملہ سے محفوظ ہوجائیں کیونکہ وہ خود تو شیطان کے خطرہ میں نہیں ہوتا مگر اس کی بھیڑیں ضرور خطرہ میں ہوتی ہیں.الغرض نبی اَعُوْذُ اس لئے پڑھتا ہے کہ شیطان کا اس پر جو حملہ بالواسطہ ہو رہا ہے وہ دور ہوجائے.کیونکہ نبی کی امت پرحملہ نبی پر ہی حملہ ہوتا ہے.پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اَعُوْذُ پڑھنا عام لوگوں کے اَعُوْذُ پڑھنے سے مختلف ہے.سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں سے پہلے اَعُوْذُ کا لفظ رکھا گیا ہے.گویا دونوں سورتیں استعاذہ کے مضمون کو لے کر آئی ہیں.یعنی خدا تعالیٰ سے انسان پناہ طلب کرتا ہے اس کے متعلق طبعاً خیال پیدا ہوتاہے کہ جب دونوں سورتیں ایک ہی مضمون پر مشتمل ہیں تو دونوں کو اکٹھا کیوں نہ کر دیا گیا اور کیوں علیحدہ علیحدہ رکھا گیا؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ سورۃ الفلق میں زیادہ تر انسان کے سوا دوسری مخلوقات کی برائیوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور سورۃ الناس میں زیادہ تر ان فتنوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے جن کی ابتدا انسانوں سے ہو.اور چونکہ یہ دونوں مضمون علیحدہ علیحدہ ہیں اس لئے ان کو علیحدہ علیحدہ سورتوں میں بیان کیا گیا ہے.قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ربّ کے معنے ہیں وہ ہستی جو انسان کو تدریجاً ترقی دیتے دیتے کمال تک پہنچاتی ہے.فَلَقٌ کے سات معنے حل لغات میں لکھے جا چکے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس جگہ پر چسپاں ہوتے ہیں.فَلَقٌ کے پہلے معنے اَلصُّبْحُ کے ہیں.پس رَبِّ الْفَلَقِ کے معنے ہوئے صبح کا رب.اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے معنے ہوتے ہیں.صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں.جیسا کہ سورۃ الفلق کے ابتدا میں لکھا جاچکا ہے کہ اس سورۃ کا تعلق سورۃ نصر سے ہے.سورۃ نصر میں یہ
Page 415
بتایاگیاتھا کہ اسلام کی فتوحات اور غلبہ کی عمارت کی وہ بنیاد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رکھی گئی اس بنیاد پر عمارت بنتی چلی جائے گی یہاں تک کہ غلبہ کی عمارت مکمل ہو جائے گی اور اگر کوئی روک پیدا ہوئی تو خس وخاشاک کی طرح اڑجائے گی.سورۃ الفلق میں یہ بتایاگیا ہے کہ اے مسلمانو! تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے غلبہ کو کمال تک پہنچائے اور پھر یہ غلبہ ہمیشہ کے لئے ہو.کوئی ایسا دشمن نہ کھڑا ہوجائے جو تمہارے غلبہ کی عمارت کو نقصان پہنچائے یا تمہارے اندر افتراق پیدا ہوجائے اور تم اس کی حفاظت نہ کر سکو.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تیرہ سال رہے.وہ زمانہ مشکلات اور مصائب کے لحاظ سے رات کے مشابہ تھا لیکن اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور کامیابی کی سحر نمودار ہونی شروع ہوگئی.اور ایک طرف اسلام کی کامیابی کے آثار نظر آنے لگے اور دوسری طرف مشکلات کم ہونے لگیں.گو صبح کی ابتدائی سفیدی پوری طرح نظر نہیں آتی تھی اور کمزور نظر والا اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن تیز نظر رکھنے والا اس کو دیکھ رہا تھا.اوروہ اس بات کی خوشخبری پاتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سورج کی روشنی ظاہر ہونی شروع ہوجائے گی اور ہر شخص اس کو دیکھ لے گا.حتی کہ آخر کار سورج نصف النہار پر چمکنے لگے گا.مدینہ میں آنے سے مسلمانوں پر فجر کا طلوع ہوا.گو مسلمانوں کو یہ فجر نظر آرہی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اُفق میں روشنی پھیل جائے گی لیکن مخالفوں کی آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر تھیں آخر یہ روشنی ظاہرہونی شروع ہوئی اور مسلمانوں کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا.حتی کہ ہجرت کے آٹھویں سال مکّہ فتح ہوا اور عرب کے لوگوں کو اسلام کی روشنی نے منور کردیا اور اسلام کی صبح کو سب لوگ دیکھنے لگ گئے.ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اے محمد رسول اللہ ! آپ کو چاہیے کہ آپ ربّ الفلق کی پناہ میں آئیں اور اس طرح اپنی امّت کے ہرفرد کو حکم دیں کہ وہ ربّ الفلق کی پناہ طلب کرے.ربّ الفلق کے الفاظ میںایک طرف یہ اشارہ ہے کہ تم دعا کرو کہ اسلام کا سورج آہستہ آہستہ اوپر آتا چلاجائے.یہاں تک کہ وسط آسمان پر پہنچ کر لوگوں کی نظروں کو خیرہ کردے.اور دوسری طرف یہ بتایا کہ اس ترقی کے زمانہ میں تمہیں خدا تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے رہنا چاہیے تاتم پر زوال نہ آئے.قرآن کریم کے مخاطب ایک طرف مومن تھے اور دوسری طرف منکر.اللہ تعالیٰ نے جہاں اس آیت میں مسلمانوں کو خوشخبری دی وہاں منکروں کو کہاکہ تم کہتے تھے کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سورج ہے تو اس کی روشنی ہونی چاہیے.خدا تعالیٰ فرماتا ہے اب ہمارے سورج کی روشنی ظاہر ہونے والی ہے.روحانی اور جسمانی علوم جو پہلے پوشیدہ تھے ظاہر ہوجائیں گے.عیوب اور خرابیاں جو تاریکی کی وجہ سے پوشیدہ تھیں اب اس روشنی کے ذریعہ نظر آنے لگیں گی.
Page 416
اور دُنیوی ترقیات جن سے لوگ پہلے محروم تھے اب دنیا کو حاصل ہوجائیں گی.جب سورج طلوع کرتا ہے تو لوگوں میں بیداری کا احساس پیدا ہوجاتا ہے.لوگ کام کاج کرنے لگ جاتے ہیں اور ترقی کے کاموں میں مصروف ہوجاتے ہیں.پھر جن چیزوں کے عیوب و نقائص اور خوبصورتی نظر نہ آتی تھی وہ نظر آنے لگتی ہے.رات کی تاریکی میں بدصورت سے بدصورت اور خوبصورت سے خوبصورت برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا.اندھیرے میں سُرخ و سفید، سیاہ، زرد، نیلا اور نسواری سب رنگ یکساں حیثیت رکھتے ہیں.لیکن جس وقت سورج چڑھتا ہے تو ان میں خودبخود امتیاز پیدا ہوجاتا ہے.بدصورت کی بدصورتی اور خوبصورت کی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے.تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب قرآن کریم کی تکمیل کے ساتھ روحانی سورج چڑھ جائے گا.اس سے عقل میں جو تیزی پیدا ہوگی اس کے ذریعہ اشیاء کا حسن و قبح معلوم ہو گا.پھر اس سے فائدہ اٹھانے والوںکے لئے ترقیات کے دروازے کھل جائیں گے.حکومت، شان و شوکت، تجارت، صنعت وحرفت غرض ہر قسم کی ترقی مسلمانوں کو حاصل ہو گی.لیکن مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح روشنی اپنے ساتھ برکتیں لاتی ہے اسی طرح بلائیں بھی لاتی ہے.مختلف قسم کی خوبصورتیاں سامنے آکر انسان کو لالچ دیتی ہیں اور اصل راستہ سے بھٹکانا چاہتی ہیں.اسی طرح روشنی صرف فائدہ کا موجب نہیں بلکہ نقصان کا موجب بھی ہوجاتی ہے.اس لئے فرمایا.دیکھو جب سورج چڑھے گا تو کئی قسم کے عیوب ظاہر ہونے کا بھی امکان ہوگا.دنیوی ترقیات آرام و آسائش اور عیش و عشرت کے ولولے قلوب میں پیداکردیتی ہیں اور دولت سے ناجائز فوائد حاصل کرنے کی خواہش انسا ن کے دل میں رونما ہوجاتی ہے.پھر روحانی علوم حاصل ہونے او ردنیا کی ان سے محرومی خود پسندی کا موجب بھی بن سکتی ہے.اسی طرح روحانی و جسمانی خطرات کا احتمال ہے.گویا روحانی علوم کی ترقی خود پسندی کی طرف لے جا سکتی ہے اور جسمانی ترقیات عیش و عشرت کی طرف.اس لئے ہم کہتے ہیں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یعنی صبح ضرور ہوگی اور مسلمانوں کو ذہنی اور روحانی ترقیات حاصل ہوں گی.سورج ضرور چڑھے گا مگر خطرہ ہے کہ ترقیات کے بدنتائج نہ پیدا ہوں.گویا وہ وقت جاتا رہا جب یہ خیال کیا جاتا تھاکہ مسلمان کس طرح ترقی کریں گے.اب تو یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان ترقیات کی وجہ سے وہ ابتلائوں میں مبتلا نہ ہوجائیں.اسی لئے مسلمانوں کو دعا سکھائی کہ تم ان جملہ اشیاء کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو جو اس نے پیدا کی ہیں.گویامِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمانو ں کو ہر چیز ملے گی کیونکہ اس میں ہر چیز کے شر سے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور ہر چیز کے شر سے بچنے کی ضرورت اسے ہی ہوسکتی ہے جسے ہر چیز حاصل بھی ہو.جو شخص گوشت کا استعمال ہی نہیں کرتا اس کی مضرتوں سے بچنے کے لئے اسے مصلح اشیاء کے استعمال کی ضرورت نہیں.
Page 417
پس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ یعنی کہہ دو میں پناہ مانگتاہوں ربّ الفلق کی یعنی صبح لانے والے اور سورج چڑہانے والے کی.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کی خرابی سے تو اس میں بتایا کہ مسلمانوں کو ہر چیز ملے گی یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس قدر نعمتیں پیدا کی ہیں ان سب سے مسلمان حصہ پائیں گے.اور دنیا کی کوئی ترقی ایسی نہیں ہوگی جو ان کو حاصل نہ ہوگی.گویا ان کی ترقیات نہایت وسیع ہوں گی.ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج ہی سے پناہ مانگیں کہ جب مسلمانوں کو ہر قسم کی کامیابیاں نصیب ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بد نتائج سے محفوظ رکھے.قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں قومی دعا کے علاوہ فردی طور پر بھی کمال تک پہنچنے کے لئے دعا سکھائی گئی ہے.چنانچہ ربّ کے معنے ہیں وہ ہستی جو انسان کو تدریجاً ترقی دیتے دیتے کمال تک پہنچاتی ہے.گویا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِمیں مضمون یہ ہے کہ اے خدا جو ظلمت کے بعد روشنی کو لاتا ہے مجھے بھی ظلمت سے نکال کرروشنی میںلا.یہ ظاہر ہے کہ اندھیر ے میں پوپھٹتی ہے اور آہستہ آہستہ روشنی ہوتی جاتی ہے اور سورج اوپر آتاجاتا ہے حتی کہ نصف النہار پر چمکنے لگتا ہے.پس فرمایا.اے وہ رب جس نے تمام ذاتی کمالات اور ترقی کے سامان جس قدر کہ ضروری تھے انسان میں جمع کر دئیے ہیں اور بتادیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو ان ذرائع کے استعمال سے کس طرح مکمل کر سکتا ہے.اے اپنی ذات میں کامل خدا مجھ کو بھی کمالات حاصل کرنے کی توفیق دے.اور مجھ کو اپنی صفتِ ربوبیت کے ماتحت اس طور پر کمال دے کہ میں بھی اسی طرح دنیا میں چمکوں جس طرح سورج وسطِ آسمان پر چمکتا ہے.اور مجھے ہر قسم کے دکھ اور مصیبت سے محفوظ رکھ اور کمال کے حصول میں کوئی مانع نہ ہو.(۲) فَلَقٌ کے دوسرے معنے ہیں اَلْـخَلْقُ کُلُّہٗ یعنی تمام مخلوقات.پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے معنے ہوں گے میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو تمام مخلوقات کا ربّ ہے یعنی جو ہر چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا ہے.اس آیت میں مخلوقات کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے لفظ فلق کو اختیار کیا گیا ہے اور خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ خلق کی نسبت فلق میں ایک زائد مفہوم پایاجاتا ہے.خلق کا لفظ صرف پیدائش پر دلالت کرتا ہے.مگر فلق کا لفظ ادنیٰ سے اعلیٰ حالت کی طرف جانے پر بھی دلالت کرتا ہے.پھر فلق کے معنے تاریکی سے روشنی کی طرف جانے کے بھی ہیں.اسی لئے فلق صبح کو بھی کہتے ہیں.پس ایک تاریک چیز جب روشنی کی طرف جاتی ہے تو اسے فلق کہتے ہیں.خالی خلق کا لفظ اگر کہا جاتا تواس میں یہ اشارہ نہ ہوتا کہ انسانی پیدائش کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت میں منتقل کرنے کا ذکر ہے.لیکن فلق کہہ کر بتادیا
Page 418
کہ مخلوق کی حالت پہلے ادنیٰ ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اعلیٰ بنا دیتا ہے پس اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں جہاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں پناہ مانگنے کے اسباب بھی بتادئیے ہیں یعنی ہم اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں جو اشیاء کا خالق و مالک ہو اور جو نقصان رساں چیزوں سے محفوظ رکھ کر ترقیات کے بلند مقام پر پہنچا سکتا ہے.جیسے اگر کسی شخص کے پیچھے کوئی کتا پڑے تو اس کتے کا مالک ہی اس کے ضرر سے بچا سکتا ہے.اب ایک تو اس میں یہ بتایا ہے کہ جس ہستی سے پناہ مانگنے کا حکم ہے وہ تمہارے آقا ومالک کی ہستی ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتادیا کہ وہ پناہ دینے والی ایسی ہستی ہے جو مخلوقات کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف لے جا سکتی ہے.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے اس کے شر سے میں اس کی پناہ چاہتاہوں.اس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں سے شر نہ پیدا ہو سکے.عام طور پر لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ بعض چیزیں اچھی ہیں اور بعض بری.مگر قرآن کریم بتاتاہے کہ یہ صحیح نہیں.ہر چیز اچھی بھی ہے اور ہر چیز بری بھی ہے.کوئی اچھی بات نہیں جس میں شر نہ ہو اور کوئی بری بات نہیں جس میں خیر نہ ہومثلا غربت و امارت ہے.اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتو دولت بھی شر پیداکرسکتی ہے اور اگر فضل ہو تو غربت بھی کوئی شر پیدا نہیں کرسکتی.حضرت سلیمان علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کتنی دولت دی وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے حساب رزق دیا ہے مگر یہ دولت ان کے لئے خیر کا موجب ہی رہی شر کا موجب نہ بنی.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ بڑے مالدار تھے.حضرت عبدالرحمٰنؓ بن عوف جب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بعد اڑھائی کروڑ روپے کی جائیداد چھوڑی.حالانکہ باقی صحابہ کا بیان ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ مالدار نہ تھے.جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰنؓ بن عوف سے بھی زیادہ مالدار صحابہؓ میں موجود تھے.مگر باوجود اس کے اس قدر مال و دولت ان کے لئے شر نہ بنی.اسی طرح صحابہؓ پر ایک وہ وقت بھی آیا جبکہ وہ غریب تھے مگر غربت کے باوجود شر کا پہلو ان کے لئے ظاہر نہ ہوا.حالانکہ دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتاہے کہ ڈاکو اور چو رجس قدر بنتے ہیں محض کنگال ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں.پس شر درحقیقت اسی وقت پیدا ہوتاہے جب انسان خدا تعالیٰ کی حفاظت سے باہر نکل جائے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ.الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں خدا تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ یہ بری چیز ہے مجھ سے دور رہے اور فلاں اچھی چیز ہے مجھے مل جائے.کیونکہ بری چیز کی برائی اور اچھی چیز کی خوبی سب اَعُوْذُ سے دُوری اور نزدیکی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے.اگر اَعُوْذُ نہ ہوتو اچھی چیز بھی بری بن جاتی ہے اور اگر اَعُوْذُ کا سہارا ساتھ ہو تو بری چیز بھی خیر کا موجب بن جاتی ہے.خدا تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھنا اور اس پر عمل کرنا کتنی اچھی چیز ہے.مگر قرآن کریم میں ہی یہودیوں کے علماء
Page 419
کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے گدھے پر کتابیں لادی جائیں.اس کے مقابلہ میں شیطان کتنی بری چیز ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہوگیا ہے اور وہ مجھے نیکی کی بات ہی کہتا ہے اس کے بھی یہی معنے ہیں کہ شیطان جو بات آپ کے دل میں ڈالنا چاہتاوہ آپ کے لئے اچھی بات بن کر آپ کے قلب میں داخل ہوتی.پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حفاظت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بتایاگیاہے کہ اگر مخلوقات کے برے پہلو سے تم بچنا چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہیں بچا سکتا ہے.کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا رب ہے اور جانتا ہے کہ کس طرح ہر شر سے بھی خیر پیدا ہوسکتا ہے اور مخلوقات میں سے کوئی شے اس کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کرسکتی.پھر مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے الفاظ سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اے مخلوقات کے پیدا کرنے والے خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں.پیدائش کے ان نقائص سے جو کسی چیز کے پیدا ہوتے وقت اس میں رہ جاتے ہیں اور اس چیز کی ترقی اور کمال کے حاصل کرنے میں روک بن جاتے ہیں.چنانچہ دنیا میںجب بھی خرابی ہو گی تین وجہ سے ہوگی.(۱) پیدائش میں نقص کی وجہ سے.(۲) انتہا خراب ہونے کی وجہ سے.(۳) یا زندگی کے درمیانی حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میںپیدائش میں نقص رہ جانے کی وجہ سے جو خرابی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے اس سے پناہ سکھائی گئی ہے.کیونکہ پیدائش میں نقص یا خرابی ہو تو تباہی آجائے گی اور مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا.مثلاً قلم ہے.انسان نے بنایا مگر اچھا نہ بنا.خراب بنا.تو اس سے کوئی اچھا نہیں لکھ سکے گا.اسی طرح ایک مکان بنایا جو ٹپکتا ہے تو اس میں کوئی آرام سے نہیں بیٹھ سکتا.یاکپڑ اپہننے کے لئے بنایا.سرد کی ضرورت تھی گرم بنالیا یا گرم کی ضرورت تھی سرد بنالیا وہ مفید نہیں ہو سکتا.یا کسی نے گھوڑا خریدا جو لنگڑا ہے وہ سفر طے نہیں کرسکتا تو جس چیز میں کوئی ابتدائی نقص ہو وہ اس مقصد کو پور انہیں کرسکتی جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے.اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ کہو میری پیدائش میں جو نقص رہ گیا ہے اس سے پناہ مانگتاہوں.انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی بداعمالیوں اور برائیوں سے بھی ورثہ پاتا ہے جس قسم کے افعال اس کے ماں باپ کرتے ہیں وہ بھی انہیں کی طرف مائل ہوجاتا ہے.اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی ملیں تو دعا مانگ لیں کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنی اولاد کے لئے بھی شیطان سے پناہ چاہتے ہیں(بخاری کتاب النکاح باب مایقول الرجل اذا اتی اھلہ).اس سے معلوم ہوا کہ بعض خرابیاں ورثہ میں پیداہوجاتی ہیں.اور پھر ظاہری لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے عام طور پر ماں باپ کے قد، علم، حوصلہ اور خیالات کو لیتے ہیں.چوری کرنے والے یا جھوٹ
Page 420
بولنے والے لوگوں کے بچے چوری اور جھوٹ کی طرف راغب ہوتے ہیں.مسلول باپ کا بچہ بھی مسلول ہوجاتا ہے پس یہ بات بالکل درست ہے کہ ورثہ میں خرابیاں اور کمزوریاں بھی ملتی ہیں اور خوبیاں بھی ملتی ہیں.چنانچہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ جس خاندان میں علم دیر تک رہے اور اس کے افراد اہلِ علم ہوتے چلے آئیں اس کے بچے وراثتاً ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی نسبت جلدی علم حاصل کرلیتے ہیں اور یہ بھی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جولوگ زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی اولاد کی آنکھیں زیادہ لمبی ہوتی جاتی ہیں.چنانچہ جن خاندانوں میں علم کا چرچاہوتاہے اور مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کی اولاد کی آنکھیں دوسروں کی نسبت لمبوتری ہوتی ہیں.یہ ماں باپ کے پڑھنے کا اثر ہوتا ہے.توماں باپ کی خوبیاں اور کمزوریاں اولاد میں آجاتی ہیں.اور جب کسی بچہ میں ماں باپ کی کمزوریاں آجائیں تواس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے لئے دنیا کی دوڑ میں روکیں پیدا ہوجاتی ہیں.اس لئے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ کہو اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.اے میرے پیداکرنے والے اور میری پرورش کرنے والے اب اگر مجھ میں ورثہ کے طور پریا کسی اور اثر سے کوئی کمزوری اور خَلقی نقص رہ گیا ہے تو اس کے اثر سے مجھے بچا.تا میں تیری رضا حاصل کرسکوں اور تیرا قرب پا سکوں.غرض اس حصۂ آیت میں ان کمزوریوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو انسان میں پیدائشی طور پر آجاتی ہیں.پھر قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان تمام مخلوقات کا ایک حصہ ہے یعنی دنیا میں جس قدر جمادات، نباتات اورحیوانات ہیں ان سب کو ترکیب دے کر خدا تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور اس کی جڑیں ان تینوں جگہوں میں پھیلی ہوئی ہیں.اور ان تینوں کاخلاصہ نکل کر انسان بنا ہے.اگر انسان کو ان تینوں جگہوں سے خوراک نہ ملے تو وہ انسان نہیں رہتا مثلاً مٹی انگور نہیں ہوتی لیکن انگور مٹی سے پیدا ہوتا ہے.اگرتم انگور کی جڑیں مٹی سے نکال لو تو انگور باقی نہیں رہے گا.کیونکہ اس کی ترقی کا ذریعہ یہ ہے کہ مٹی بھی ہو اور انگور کی بیل بھی.اگر مٹی نہ ہو تو انگور کی حیثیت باقی نہیں رہتی اور اگر مٹی ہی ہو اور انگور نہ ہوتو مٹی کی کوئی قدروقیمت نہیں.اسی طرح اگر نباتات، جمادات اور حیوانات کے نتیجہ میں انسان پیدا نہ ہوتا اور اگرخالی اسی حد تک یہ چیزیں رہتیں تو یہ سب فضول اور لغو ہوتیں.جیسے مٹی فضول اور لغو ہے بغیر خربوزہ کے بغیر آم اور انگور کے.پس وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانوں کو روحانی امور کی طرف تو لے جاتے ہیں مگر طیّبات سے پرہیز کرا کر اور ان کی ان ضروریات سے علیحدہ کرواکر جو خدا تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگائی ہیں.وہ اس امر کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ طیّبات وہ زمین ہے جس میں روحانیت کا پودا اُگاکرتا ہے اور اسی زمین میںنشو ونما پاکر یہ پودا روحانیت کے میوے لاتا ہے.یہی چیز ہے جسے
Page 421
اسلام پیش کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ نباتات، جمادات اور حیوانات کے ملانے سے جو خلاصہ پیدا کیا گیا ہے اس کے پھل کا نام انسان ہے.جب تک یہ نہ ہو انسانیت کا پودا پنپ نہیں سکتا.اور جب تک یہ خیال نہ رکھا جائے کہ انسانیت کی جڑیں جمادات، نباتات اور حیوانات سب میں ہیں اس وقت تک یہ پودا سرسبز نہیں رہ سکتا.سورۃ فلق کی آیات قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں ہمیں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان مخلوقات کا ایک جزو ہے.وہ جمادات، نباتات، حیوانات سے علیحدہ نہیں ہے.اگر ہم ان چیزوں سے علیحدہ ہوتے تو ہمیںیہ حکم نہ دیا جاتا کہ ہم ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگیں.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی برائی ہم تک پہنچ سکتی ہے اس لئے ہمیں ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے ہر وقت دعا کرنی چاہیے.غرض ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمام جمادات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی.تمام نباتات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی.اور تمام حیوانات سے ہمیں شر بھی پہنچ سکتا ہے اور خیر بھی.اور ہماری جڑیں ان تینوں کرّوں میں دبی ہوئی ہیں.ان حالات میں ہمیں دعا سکھائی کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جماداتی، نباتاتی اور حیوانی ہستی کا خیال رکھنا چاہیے.جب تک جڑوں کوپانی نہ دیا جائے اس وقت تک درخت سرسبز نہیں رہ سکتا.اسی طرح انسان کی روحانیت اعلیٰ درجہ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ جمادات، نباتات اور حیوانا ت میں سے طیّب اشیاء کو استعمال نہیں کرتا.اور ان کے شر سے بچتا نہیں ہے.اسی طرح درخت میں بعض امراض اس کی جڑوں سے پیداہوتی ہیں اور بعض پتوں سے.سورۃ فلق کی ان آیات میں ہمیں ان امراض سے بچنے کا علاج بتایا ہے جو ہمیں جڑ سے پہنچ سکتی ہیں.پس فرمایا تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ خدا جس نے تمام مخلوقات پیدا کی ہے ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں.تاکہ ہمیں تمام مخلوقات کی خیر تو ملتی رہے لیکن ان کا شر ہم تک نہ پہنچ سکے.کیونکہ ان چیزوں کا خالق ہی اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے وگرنہ نہیں.قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں ایک اور اہم امر کی طرف بھی اُمّتِ مسلمہ کے ہر فرد کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور وہ یہ کہ سورۃ الفلق سے پہلی سورۃ یعنی سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توحید کامل کا سبق دیا تھا.اس سورۃ کے بعد قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اے وہ شخص جو ایمان لایا ہے ہماری ذات پر، ہمارے کلام پر اور اس میں سے بھی ہمارے قرآن پر.ہم اسے کہتے ہیں کہ جائو اور جاکر لوگوں میں اپنے اس ایمان کا اعلان کرو اور کہو اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.تم لوگ دنیا میں بھروسہ کرتے ہو اپنے ماں باپ پر.تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو اپنے رشتہ داروں او ردوستوں پر.تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو اپنے خاندانوں پر اور جتھوں پر.تم لوگ بھروسہ رکھتے ہو اپنے محلّہ کے لوگوں پر اور محلّہ کے چوہدریوں پر.تم بھروسہ رکھتے ہو اپنی حکومتوں پر.
Page 422
اور تم بھروسہ رکھتے ہو اپنے ملک کی فوجوں پر اور اپنے ملک کے استادوں پر جو لوگوں کو جہالت سے بچاتے ہیں اور ملک کے ڈاکٹروں پر جو اہل ملک کی صحت کی ترقی میں مدد دیتے ہیں اور ملک کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں.غرضیکہ تم لوگ ان چیزوں پر بھروسہ رکھتے ہو.مگر میرا ان میں سے کسی پر بھروسہ نہیں.بلکہ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.ان کی طرف سے توجہ ہٹاکر میں نے ربّ الفلق کے ساتھ لَو لگا لی ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے.گو اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ چھوٹا سا فقرہ ہے لیکن اس کو کہنے والا گویا ساری دنیا کو چیلنج دیتا ہے اور ایک ایسا دعویٰ کرتا ہے جس کے بعد دنیا کا ہر فرد اس کے اعمال کا نگران بن جاتاہے.وہ ایک مجلس میں جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پرواہ نہیں حکومت کی، ماں باپ کی، بھائی بہنوں کی، دوستوں رشتہ داروں کی.پھر وہ دوسری مجلس میں جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کیونکہ اس کو قُلْ کے لفظ میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر مجلس میں جائے اور یہ اعلان کر دے کہ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میںنے ربّ الفلق یعنی مخلوقات کے پیداکرنے والے کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا ہے اور اسی لئے اب دنیوی اسباب پر میرا بھروسہ نہیں ہے.پھروہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت تیسری مجلس میںجاتاہے اور یہی کہتا ہے اور اس کے بعد چوتھی مجلس میں جاتا ہے اور یہی کہتا ہے اور اس طرح ہر شخص اس کے اعمال کا نگران بن جاتا ہے اور پھر جب اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے بعد وہ اگر کسی تحصیلدار، تھانیدار یا کسی اور کے سامنے جاتااور اسے سلام کرتاہے اور اس سے اپنی مشکلات کے دور کرنے میں مدد مانگتا ہے توان لوگوں میں سے جن کے سامنے اس نے اپنے آپ کو ربّ الفلق کی پناہ میں دے دینے اور دنیوی رشتوں سے قطع تعلق کا اعلان کیا تھا.ہرایک اسے شرمندہ کرے گا کہ تُو نے دعویٰ تو بہت بڑا کیا تھا مگر عمل کے وقت اپنے دعویٰ کو سچا کر کے نہ دکھا سکا.تو اللہ تعالیٰ نے اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سے پہلے قُلْ کا لفظ لاکر ہر مسلمان کو گویا یہ ہدایت دی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی صحیح توحیدکا علم حاصل کرچکے ہو تو ہرمجلس میں جاکر یہ اعلان کرو.تا ہر شخص تمہارا نگران بن جائے اور جب بھی دیکھے کہ تمہارا عمل اس کے خلاف ہے تووہ تم کو شرمندہ کر سکے ایک شخص منہ سے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ربّ الفلق کی پناہ میں دے دیا.مگر جب اس کے گھر میں بیماری آتی ہے وہ خود یا اس کے بیوی بچے بیمار ہوجاتے ہیں تووہ گھبرا کر رونے لگ جاتا ہے.جب اس پر قرضہ ہوجائے تووہ گھبرا کر رونے لگتا ہے افسر ناراض ہوجائیںتو گھبراکر رونے لگتاہے.استاد بگڑ جائے تو گھبرا کر رونے لگتا ہے اس پر ہر شخص اسے جھوٹا کر سکتا ہے کہ تم تو خدا تعالیٰ کی توحید پر قائم ہو نے کے دعویٰ دار تھے تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ سوائے خدا تعالیٰ کے مجھے کسی کی پرواہ نہیں پھر یہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر مصیبت سے تم ڈر رہے ہو.پس سورۃ فلق کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن سے یہی کہا ہے کہ اگر تمہارے اندر واقعی ایمان پیداہوچکا ہے تو ساری دنیا کو چیلنج
Page 423
دے دو اور سب لوگوں کے سامنے دنیا سے بے پرواہ ہوکر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی پناہ میں دے دینے کا اعلان کردو.تا جب تمہارا عمل اس دعویٰ کے خلاف ہو تو ہر شخص یہ سمجھ سکے کہ یہ جھوٹا ہے.منہ سے تو کچھ کہتا ہے مگر عمل کچھ اور ہے.اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کی آیت میں قُلْ کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنے اس دعویٰ پر ساری دنیا کو گواہ بنالو.انسان خدا تعالیٰ کے حضور جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا میں نے تمام رشتوں سے قطع تعلق کر لیا اور اپنے ہاتھ پائوں باندھ کر اپنے آپ کو تیرے حضور ڈال دیا ہے.مگر اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ یہ بات ہم کو آکر نہ کہو بلکہ جائو اور دنیا کے سامنے یہ بات بیان کرو اور اسے اس بات پر گواہ بنائو کہ تم خدا تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو.تا جب تمہارا عمل تمہارے اس دعویٰ کے خلاف نظر آئے تو لوگ کہہ سکیں کہ تم بڑے جھوٹے اور مکا ر ہو.منہ سے تو کچھ کہتے ہو مگر عمل کچھ ہے.تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قُلْ کا لفظ رکھ کر بتادیا کہ اب تم سارا قرآن کریم پڑھ چکے اب تمہارے دل کا ایمان پختگی حاصل کر چکا ہے اب اسے مخفی نہیں رکھا جاسکتا جو بات تم ہمارے سامنے آکر کہتے ہو اسے یا تو کھلے میدان میں ظاہر کرو.لوگوں کو اس پر گواہ بلکہ قاضی اور جج بنائو.تاجب تمہارا عمل اس کے خلاف ہو تو وہ ملامت کر سکیں.اور یاپھر اس دعویٰ کو ترک کردو.ہم تمہارے اس دعویٰ کو نہیں مانتے جو تم علیحدگی میں ہمارے حضور کرتے ہو اور نماز پڑھتے وقت کہتے ہو کہ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتاہوں.تمہارے اس دعویٰ کے معنے تویہ ہیں کہ تمام مخلوق سے تمہارا رشتہ ٹوٹ چکا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوگیا.اب تمہارا بھروسہ ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ داروں، قوم و حکومت پر نہ ہوگا.ان سب کے تعلق ٹوٹ کر اب خدا تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا اور یہ ایک ایسادعویٰ ہے جس کی حقیقت تم پر اس وقت تک واضح نہیں ہوسکتی جب تک کہ تم لوگوںکو اس پر گواہ نہ بنالو اور جو انسان اس مقام پر کھڑا ہو وہ کس طرح اطمینان کا سانس لے سکتا ہے جب تک وہ اپنے عمل سے اس دعویٰ کی تصدیق نہ کردے.بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کام کے لئے دعا کریں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہوسکے تو فلاں شخص سے سفارش بھی کرا دیں.حالانکہ دعا کے ساتھ ہی سفارشی خط چاہنا توکّل کے خلاف ہوتا ہے.بلکہ مومن کے لئے تو یہ شرم سے زمین میں گڑ جانے کا مقام ہے کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو اسے نہ بادشاہوں پر بھروسہ کرنا چاہیے اور نہ کسی پارلیمنٹ پر اور نہ کسی فوج یا حکومت پر اور نہ ملک کے مدبّروں پر.مومن تو دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ میرا ہاتھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد اگر وہ کسی کے پاس جاتا اور اس سے باصرار کہتا ہے کہ میرا فلاں کام کردو.(بغیر توکّل اور اصرار کے اس خیال کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ
Page 424
نے سامانوں سے کام لینے کا حکم دیا ہے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے جس پر اس کا حق ہے مدد چاہے تو یہ گناہ نہیں.گناہ یہ ہے کہ وہ سفارش پر توکّل کرے اور جب اس کی خواہش پوری نہ ہو تو اسے صدمہ ہو اور وہ اصرار کرے کہ کسی طرح اس کو سفارشی چٹھی مل جائے ) تو اس سے زیادہ ذلیل کون ہو سکتا ہے.قاضی ظہورالدین صاحب اکمل کے والد مولوی امام دین صاحب کو تصوّف سے بہت شغف تھا.احمدی ہونے سے پہلے وہ صوفیاء کے مرید تھے.اس لئے جب بھی انہیں موقعہ ملتا مجھ سے وہ یہ بات کہتے کہ فلاں صوفی صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے عرش پر سجدہ کیا.فلاں صوفی صاحب تھے جنہوں نے فلاں آسمان پر سجدہ کیا.فلاں نے سجدہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا.مگر احمدیت میں یہ بات نظر نہیں آتی.میں اس کے متعلق ان کو کئی دلائل دیتا.مگر سال چھ ماہ کے بعد پھر یہی سوال کردیتے کہ وہ چیز ابھی نہیں ملتی جو صوفیاء بتاتے چلے آئے ہیں.ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا جواب سمجھایا.میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وہ جو عرش پر سجدہ کرتے ہیں یا آسمان پر کرنے والے ہیں وہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام سے درجہ میں چھوٹے ہیں.وہ کہنے لگے میں مانتا ہوں کہ احمدیت میں سب کچھ ہے مگر عرش پر سجدہ کرنا بھی تو بہت بڑی بات ہے.میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ وہ عرش پر سجدہ کرتے ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کا کوئی ظاہری ثبوت بھی تو ہونا چاہیے.ایک انسان بھی اپنے ساتھ ادنیٰ جوڑیا تعلق رکھنے والے کو ذلیل نہیں کرتا.میں نے ان سے کہا.کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت مسیح موعودعلیہ السلام پر کتنا بار تھا ابتداء میں بیسیوں اور بعد میں سینکڑوں تک مہمان روزانہ لنگر سے کھانا کھاتے تھے اور مہمان نوازی کا خرچ پندرہ سَو سے اڑھائی ہزار روپیہ ماہوا رتک تھا.مگر آپ کی کوئی آمد مقرر اور معیّن نہ تھی.بے شک جماعت کے دوست چندہ دیتے تھے لیکن یہ کوئی مقرر اور معیّن آمد تو نہ تھی مگر دیکھئے باوجود اس قدر کثیر اخراجات کے اور آمد کی معیّن صورت نہ ہونے کے حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کو خدا تعالیٰ پر کیسا توکل تھا اور خدا تعالیٰ کس طرح آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا.کیا یہ عرش پر سجدہ کرنے والے لوگ بھی اس توکّل کے مقام پر تھے؟ مولوی صاحب اس بات کو سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے کہ آج میری سمجھ میں یہ بات آگئی ہے کہ یہ عرش پر سجدہ دھوکہ ہی تھا.یہ عرش پر سجدہ کرنے والے صاحب غلّہ نکلنے کے زمانہ میں زمینداروں سے کہا کرتے تھے کہ کچھ غلّہ ہمیں بھی بھجوانا.میںنے ان سے کہا کہ بس دیکھ لیں کہ یہی فرق سچے متوکّل اور جھوٹے متوکّل میں ہوتا ہے.بہر حال مومن خدا تعالیٰ پر توکّل کرنے والا ہوتا ہے اور جب وہ لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں رَبِّ الْفَلَقِ کی پناہ میں آتا ہوں تو پھر وہ بندوں کی طرف نگاہ نہیں کرسکتا.بلکہ خدا تعالیٰ پر ہی یقین رکھتا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے آپ کو کیا
Page 425
پتہ ہوتا کہ کل روپیہ آجائے گا یا نہیں مگر خرچ ہوتا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے کبھی تنگی نہ آنے دی.تومومن بندوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا.بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکّل رکھتا ہے.آگے اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ کسی کا امتحان فاقہ دے کر لینا چاہے تو لے لے یا کسی کو فراخی دے کر آزمانا چاہے تو آزمالے.شیخ عبدالقادر صاحب جیلانیؒ کے متعلق لکھا ہے کہ بہت اعلیٰ لباس پہنتے تھے اور اعلیٰ کھا نا کھاتے تھے.بعض اوقات ایک ایک جوڑا ان کا ایک ایک ہزار دینار یعنی اڑھائی تین ہزار روپے کا ہوتا تھا بعض نادان ان پر اعتراض بھی کرتے تھے مگر آپ جواب دیتے کہ میں توجو کپڑا پہنتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنتاہوں.میں تو کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہیں کہتا کہ اے عبدالقادر تجھے میری ذات کی قسم یہ کپڑا پہن(گلدستہ کرامات ۸۰).تو بندہ کے توکّل کے یہ معنے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا ہوجائے.چنانچہ فرمایا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.جا دنیا کے لوگوں سے کہہ دے کہ میں اب خدا تعالیٰ کا ہو گیا ہوں مجھے تمہاری پرواہ نہیں.اور اگر لوگ اس دعویٰ کی وجہ سے تم پر حملہ کرنے کے لئے اٹھیں تو تم کہنا کہ میں تمہاری ایذائوں سے بے نیاز ہوں اور ان کے لئے بھی اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں.(۳)تیسرے معنے فلق کے جہنم کے ہیں.ان معنوں کے اعتبار سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں جہنم کے پیدا کر نے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور ان شدائد سے بھی جو اس جہنم میں پیدا کئے گئے ہیں.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ جَنَّتٰنِ(الرّحـمٰن:۴۷) کہ جو خدا کے بندے ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی جنت ملتی ہے اور آخرت میں بھی.اور پھر نبی کے ذریعہ جو نظام قائم ہوتا ہے اس کو بھی جنت کہا گیا ہے.جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا.اسْکُنْ اَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّۃَ.(البقرۃ:۳۶) کہ اے آدم تم اور تمہارے ساتھی اس نظام میں رہو جس میں رہنے کا ہم نے تمہیں حکم دیا ہے.کیونکہ اگر تم اس میں رہو گے تو تمہارے لئے یہ دنیا جنت بن جائے گی.قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کو بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم ہیں اور آپ کے ذریعہ بھی ایسا نظام جاری کیا گیا ہے جو اس زمین کے رہنے والوں کو جنّتی بنادے گا.اور وہ آرام کی زندگی بسر کریں گے.پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے مسلمانو ! تم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کر کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تمہیں انفرادی اور اجتماعی طور
Page 426
پر جنّت میں داخل کردیا ہے.كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ( اٰلِ عمران:۱۰۴) تم آگ کے کنارے پر تھے تم کو نکا ل کر جنّت میں داخل کردیا.اللہ نے تمہیں ذہنی اور قلبی سکون عطا کیا.تم ایک ہاتھ پر جمع ہوگئے تم میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا وہ اعلیٰ مقام پیدا ہو گیا کہ تمہارے لئے یہ دنیا جنت بن گئی.تم کو خدا تعالیٰ مل گیا اور تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گیا.پس ان نعمتوں کو یاد رکھو اور جہنّم کے رب کی پناہ میں آئو.اور اس کے شدائد سے بچنے کے لئے بھی اس کی پناہ چاہو.تاکہ جہنّم کبھی تمہارے قریب نہ آئے.یعنی ایسی حالت پیدا نہ ہو کہ تمہارا انفرادی اور قومی اطمینان ختم ہوجائے.تمہارے اندر لڑائی جھگڑے پیدا ہوجائیں.تم قرآن کریم کی تعلیم کو چھوڑ دو اور یہ دنیا بھی تمہارے لئے جہنم بن جائے اور آخرت میں بھی جہنم دیکھنا پڑے.(۴) چوتھے معنے الفلق کے دوپہاڑیوں کے درمیان کے میدان کے ہوتے ہیں.بعض اقوام ایسی ہیں جو افراط کی طرف چلی گئی ہیں اور بعض تفریط کی طرف.لیکن اللہ تعالیٰ کے حصول اور دنیا میں امن و امان کا اصل طریق میانہ روی ہے.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امّت وسط قراردیا ہے کہ ان کی تعلیم میں نہ افراط پایا جاتاہے اور نہ تفریط.اور جو ایسی تعلیم ہو وہ اعلیٰ درجہ کی ہوگی اور اس سے دنیا میں امن پیدا ہوگا.تو فرمایا.قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کہ اے مسلمانو!کہوہم اس رب کی پناہ چاہتے ہیں جس نے افراط اور تفریط کی دوپہاڑیوں کے درمیان اسلام جیسا خوبصورت میدان بنایا ہے.جہاں دنیا کو چین اور آرام حاصل ہوسکتا ہے گویا ان آیات میں بتایا ہے کہ تم اس خدا کی پناہ چاہو جس نے اسلام جیسے بہترین مذہب کو بھیجا.جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل انسان بھیجا اور جس کے ذریعہ سے تم کو قرآن جیسی کامل تعلیم ملی.تم اس بات سے پناہ چاہو کہ تمہارے لئے کوئی شر پیدا نہ ہوجائے.یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی وقت کوئی ایسا شر پیدا ہو جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی بہترین تعلیم سے علیحدہ ہوجائو.اسلام کو چھوڑ دو او رمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے کنارہ کشی کر لو.جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم مشکلات میں مبتلاہوجائو اور تمہاری زندگی تمہارے لئے مشکل ہوجائے.اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے اور اس کی ربوبیت سے فیض پانے کا صحیح طریق میانہ روی ہے نہ انسان افراط کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے اور نہ تفریط والے راستے کو اختیا رکر کے.ہاں اگر میانہ روی کو اختیار کرتا ہے تو خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے.لیکن اس تک پہنچنے میں بہت سی روکیں ہیں اور درحقیقت دنیا کا ہر ذرّہ اس تک پہنچنے میں روک ہے.جولوگ ناکام رہتے ہیں وہ اسی لئے رہتے ہیں کہ وہ سمجھتے
Page 427
ہیں کہ ہم نے فلاں روک کو دور کردیا.مگر درحقیقت اس روک کے علاوہ کئی اور روکیں بھی ہوتی ہیں.جن کی طرف ان کا خیال بھی نہیں جا سکتا.پس کامیاب انسان وہی ہوتاہے جو کہتا ہے کہ دنیا کا ذرّہ ذرّہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے.وہ اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ بیوی بچے، استاد، شاگرد، مال جائیداد، مرتبہ عزّت، عمل، بے عملی، غرض ہرچیز سے ہوشیار رہتا ہے.کیونکہ کبھی انسان اپنے کسی عمل کی وجہ سے محروم ہوجاتا ہے اور کبھی کسی بے عملی سے اور کبھی علم کی وجہ سے محروم رہ جاتاہے کبھی جہالت سے.اس لئے کامیابی کا حقیقی خواہاں وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کے حضور گرتا ہے اور کہتا ہے اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اے خدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے راستہ میں ہلاکت اور رکاوٹیں کہاں کہاں سے آرہی ہیں.اس لئے اے خدا جو خالق ہے تمام چیزوں کا ان کے شر سے مجھے بچا.کیونکہ ان کے شر کا تجھے ہی پتہ ہے.پس یہ ترقی کا پہلا زینہ ہوتا ہے کہ انسان ہر ذرّہ سے حتی کہ اپنے نفس سے بھی ڈرتا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہے.پھر یہی نہیں کہ مومن اپنے ایمان کے متعلق ڈرتا ہے کہ ایسانہ ہو میرے دل میں تکبر پیدا ہوجائے اور میں مارا جائوں.بلکہ وہ قرب الی اللہ سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ یہ بھی ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے جیسے کہ بلعم کے لئے ہو گیا تھا.اسی خطرہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ اِلَّا اِلَیْکَ کے الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے لئے ہلاکت و وبال اسی راستہ سے آرہا ہو جو ہم نے تجھ تک پہنچنے کے لئے اختیار کیا ہے.اس لئے ہماری نجات کی صورت تُوہی ہے تُو ہمیں اپنی پناہ میںلے لے.پس مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ سے بتایا کہ انسان کو ہر ذرّہ سے ڈرنا چاہیے اور چونکہ انسان کو علم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز اس کی ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے اس لئے ان اشیاء کے پیدا کرنے والے خدا سے ہی پناہ مانگنی چاہیے.(۵) الفلق کے پانچویں معنے اس لکڑی کے ہیں جس میں مجرموں کو قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے.پس ان معنوں کے اعتبار سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے یہ معنے ہوں گے کہ میں قید خانوں کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں.اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں قید خانے میں پڑجائوں اور اس کی شدائد اور مشکلات مجھے برداشت کرنی پڑیں.گویا اس میں قومی لحاظ سے بھی دعا سکھائی گئی ہے اور فردی لحاظ سے بھی.یعنی ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم آپس میںلڑ پڑے اور ایک دوسرے کو قید خانوں میں ڈال کر شدائد میں مبتلا کردے.یا ایسا نہ ہو کہ کوئی مخالف حکومت اٹھے اورا سلامی حکومت کو برباد کردے اور مسلمانوں کو قید وبند کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے اور مسلمانوں کا آرام ختم ہوجائے
Page 428
اسی طرح فردی لحاظ سے یہ دعا سکھائی کہ تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ تم دانستہ یا نادانستہ کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھو جس سے تمہیں قیدو بند کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑے.پس ان مشکلات سے وہی خدا بچا سکتا ہے جو ہر ایک کے قلب پر حکومت کرتا ہے اور جو حقیقی حکمران ہے تاکہ اگر بالفرض ایسا وقت آبھی جائے تو اللہ تعالیٰ قید خانوں کے مالکوں کے دلوں کو بدل دے اور وہ سختی کی بجائے نرمی سے پیش آئیں.(۶) الفلق کے چھٹے معنے اس دودھ کے ہیں جو دودھ پینے کے بعد پیالے کے آخر میں تھوڑا سا بچ جاتا ہے.ان معنے کے اعتبار سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کا یہ مفہوم ہوگاکہ اے خدا تُو نے مجھے وہ کامل تعلیم قرآن کریم کے ذریعہ سے دی ہے جو اس پیالہ کی مانند ہے جو دودھ سے بھرا ہواہو.ایسا نہ ہو کہ کسی وقت میری کمزوریوں کی وجہ سے میرے پاس اس تعلیم میں سے تھوڑا ساحصہ رہ جائے اور روحانی طور پر امیر ہونے کے بعد میں غریب ہوجائوں.احادیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معراج کی رات کو دودھ، پانی اور خمر پیش کئے گئے.نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا تب جبریل نے کہا کہ یارسول اللہ ! اگر آپ پانی اور خمر کو لے لیتے تو آپ کی اُمّت تباہ ہوجاتی.آپ نے دودھ کو لے کر فطرتِ صحیحہ کے مطابق کام کیا ہے(بخاری کتاب التفسیر بَابُ قَوْلِهِ أَسْـرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا) پس دودھ سے مراد قرآنی تعلیم ہے جو فطرتِ صحیحہ کے مطابق ہے.پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں بتایا کہ مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآنی تعلیم پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق دے اوروہ اس تعلیم کی حفاظت کرتے رہیں اور ایسا نہ ہو کہ کسی وقت اس پر عمل کو چھوڑ کر اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے پاس تھوڑا سا دودھ رہ جاتا ہے.دنیا میں جب کوئی شخص امیر ہونے کے بعد پھر غریب ہوتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کی زندگی اس کے لئے دوبھر ہو جاتی ہے.پس انفرادی لحاظ سے بھی اس میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اور جن کے ذریعہ سے وہ آرام و اطمینان کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ نعمتیں ہاتھ سے جاتی رہیں اور اس کی زندگی کے دن مشکل سے کٹیں.پھر اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایسا نہ ہو اسلام کے غلبہ کی وجہ سے جو مسلمانوں کو رفاہیت حاصل ہے وہ کسی وقت مسلمانوں کی حکومت کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے تکلیف میں بدل جائے اور مسلمان کڑھتے رہیں.بلکہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ خود دستگیری کرے اور پھر سے سامان پیدا کر دے کہ مسلمانوں کی کمزوری طاقت سے اور ضعف کے دن شوکت سے بدل جائیں.(۷) ساتویں معنے الفلق کے اَلْاَنْـھَارُ کے بھی ہیں.اور ربّ الفلق کے معنے ہوں گے دریائوں کارب.اس
Page 429
لحاظ سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ کہو میں انہار یعنی دریائوں کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں.اس بات سے کہ ان کے ذریعہ سے مجھے یا میری قوم کو کوئی شر نہ پہنچ جائے.یہ ظاہر ہے کہ دریائوں کے ذریعہ سے مُلک سیرا ب ہوتے ہیں اور ان پر مُلکوں کی خوراک کا انحصار ہوتا ہے.اگر صحیح رنگ میں ان سے پانی ملتا رہے.دریائوں سے نہریں نکالی جائیں اور ان نہروں سے زمینوں کو سیراب کیا جائے تو وہ مُلک کے لئے مفید ہوتے ہیں.لیکن اگر دریائوں میں طغیانی آجائے تو نہ صرف یہ کہ فصلیں تباہ ہوجاتی ہیں.بلکہ لوگ بھی ڈوب کر مر جاتے ہیں.پس دریا ایک مفید چیز ہے جس پر زندگی کا دارومدار ہے لیکن جب اس کا مضر پہلو ظاہر ہوتا ہے تو وہ زندگی بخش ہونے کی بجائے زندگی ختم کرنے کا ذریعہ ہوجاتا ہے.درحقیقت ہر چیز کا یہی حال ہے.اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ جسمانی اور روحانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ان کے لئے فائدہ بخش ہو اور اس کے مضرات سے اللہ تعالیٰ خود ہی بچاتا رہے اور ایسا نہ ہو کہ دین کے علوم کی فراوانی جو ان کو حاصل ہوئی ہے وہ انہیں مغرور بنادے اور دوسرے بنی نوع انسان کو ذلیل سمجھنے لگ جائیں اور وہ چیز جو خدا تعالیٰ کے طفیل ان کوملی ہے وہ اسے ذاتی قابلیت کا نتیجہ نہ سمجھنے لگ جائیں.وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ۰۰۴ اور اندھیرا کرنے والے کی ہر شرارت سے (بچنے کے لئے ) جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے.حلّ لُغات.غَاسِقٌ.غَاسِقٌ غَسَقَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے اور غَسَقَتْ عَیْنُہٗ غُسُوْقًا کے معنے ہیں دَمَعَتْ وَقِیْلَ اِنْصَبَّتْ وَقِیْلَ اَظْلَمَتْ.آنکھ آنسوئوں سے ڈبڈبا آئی.اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جب آنسو آنکھ سے ٹپک پڑیں اور آنکھ کے سامنے اندھیرا ہوجائے تو اس وقت غَسَقَتْ عَیْنُہٗ کا فقرہ بولتے ہیں اور جب غَسَقَتِ السَّمَآءُ غَسْقًا کہیں تو معنے ہوں گے اِنصَبَّتْ وَاَرَشَّتْ یعنی بادلوں نے موسلادھار پانی برسایا اور غَسَقَ اللَّبَنُ کے معنے ہیں.اِنْصَبَّ مِنَ الضَّـرْعِ دودھ زیادتی کی وجہ سے پستان سے ٹپک پڑا اور غَسَقَ الْـجُرْحُ کے معنے ہوتے ہیں سَالَ مِنْہُ شَیْءٌ اَصْفَرُ کہ زخم سے زرد رنگ کی پیپ بہہ پڑی اور جب غَسَقَ اللَّیْلُ غَسْقًا کہیں تو مراد ہوگی کہ اِشْتَدَّتْ ظُلْمَتُہٗ.رات کی تاریکی سخت ہوگئی.(اقرب)
Page 430
اَلْغَاسِقُ کے معنے ہیں اَلْقَمَرُ وَاللَّیْلُ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَاشْتَدَّتْ ظُلْمَتُہٗ یعنی غَاسِقُ کے معنے چاند کے ہیں اور رات کے بھی.جب اس کی تاریکی زیادہ ہوجائے.قِیْلَ اَیِ اللَّیْلُ اِذَا دَخَلَ.اسی طرح کہا گیا ہے کہ غَاسِق کے معنے رات کے ہیں جب وہ تاریکی پھیلا دیتی ہے اَوِالثُّرَیَّا اِذَا اَسْقَطَتْ لِکَثْرَۃِ الطَّوَّاعِیْنِ وَالْاَسْقَامِ عِندَ سُقُوْطِھَا.بعض کہتے ہیں کہ غَاسِقٌ کے معنے ثریا ستارے کے ہیں جبکہ وہ اپنی اصلی جگہ سے ہٹ جائے اور اس کے نتیجہ میں مختلف قسم کی امراض پیدا ہوں.(اقرب) مفردات میں غَسَقُ الَّیْلِ.شِدَّۃُ ظُلْمَتِہٖ.یعنی غَسَقُ الَّیْل کے معنے ہوتے ہیں رات کی تاریکی.قَالَ مِنْ شَـرِّ غَاسِقٍ.....ذٰلِکَ عِبَارَۃٌ عَنِ النَّائِبَۃِ بِالَّیْلِ کَالطَّارِقِ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ کے الفاظ فرمائے ہیں ان میں غَاسِقٍ سے مراد وہ مصیبت یا حادثہ ہے جو رات کو آئے.وَقِیْلَ اَلْقَمَرُ اِذَا کَسَفَ.بعض لوگوں نے کہا ہے کہ چاند کو بھی غاسق کہیں گے جبکہ اس کی روشنی جاتی رہے اور اس کو گرہن لگ جائے.وَقَبَ.وَقَبَ: وَقَبَتِ الشَّمْسُ وَغَیْرُھَا کے معنے ہوتے ہیں غَابَتْ سورج غائب ہوگیا.اور جب وَقَبَ الرَّجُلُ وَقْبًا کہیں تو معنے ہوں گے دَخَلَ فِی الْوَقْبِ یعنی فلاں شخص اندھیرے میں داخل ہوگیا.وَغَارَتْ عَیْنَاہُ اور وَقَبَ الرَّجُلُ کے یہ بھی معنے ہیں کہ اس کی آنکھیں اندر دھنس گئیں.اور وَقَبَ الظَّلَّامُ عَلَی النَّاسِ کے معنے ہوتے ہیں دَخَلَ وَانْتَشَـرَ کہ لوگوں پر اندھیرا چھا گیا.اور جب وَقَبَ الْقَمَرُ کہیں تو اس کے معنے ہوں گے.دَخَلَ فِی الْکُسُوفِ کہ چاند کسوف میں داخل ہوگیا.نیز اَلْوَقْبُ کے معنے ہیں نُقْرَۃٌ فِی الصَّخْرَۃِ یَـجْتَمِعُ فِیْـھَا الْمَآءُ.چٹان کا وہ گڑھا جس میں پانی جمع ہوتا ہے.اَلْکُوَّۃُ الْعَظِیْمَۃُ فِیْـھَا ظِلٌّ.وہ بڑا گڑھا جس میں سایہ ہوتا ہے.(اقرب) پس وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کے معنے ہوں گے (۱) میں پناہ چاہتاہوں رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ اندھیرا چھا جائے.(۲) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب سورج غرو ب ہوجائے.(۳) میں پناہ چاہتا ہوں اس وقت کے شر سے جب چاند اور سورج کو گرہن لگے.(۴) میں پناہ چاہتاہوں اس وقت کے شر سے جب کہ فراخی کے بعد تنگی ہوجائے.(۵) میں ان حوادث سے پناہ چاہتا ہوں جو رات کے وقت آئیں.(۶) میں اس وقت کے شر سے پناہ چاہتاہوں جب کہ انسان گڑھے میں داخل ہو جائے.تفسیر.قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بتایا جا چکا ہے کہ ان آیات میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اسلام کا وہ غلبہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شروع ہوا وہ مکمل ہوکررہے گا
Page 431
اور یہ کہ مسلمانوں کو ہر قسم کی نعمتیں حاصل ہوں گی اور پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں ایک طرف تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ موعود غلبہ ان کو جلد حاصل ہوجائے اور دوسری طرف انہیں اللہ تعالیٰ سے اس بات سے پناہ طلب کرنی چاہیے.ایسانہ ہو کہ وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہوجائیں جن میں عام طور پر حکمران اقوام مبتلاہوجاتی ہیں اور یہ کہ ان کو مال کی فراوانی تعیّش میں مبتلا نہ کردے یا وہ جاہ وحشمت کے لئے آپس میں لڑنا بھڑنا نہ شروع کردیں.ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ یعنی میں غاسق کے شر سے پناہ مانگتاہوں جب کہ وہ وقوب اختیا ر کرلیتا ہے.جیسا کہ حلّ لغات میں بتایا جا چکا ہے غَاسِق کے معنے رات کے ہیں اور وَقَبَ کے معنے اندھیرے اور ظلمت کے چھا جانے کے ہیں.اسی طرح غَاسِق کے معنے سورج کے ہیں اور وَقَبَ کے معنے غائب ہونے کے ہیں.پس ان معنوں کے اعتبا ر سے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کا مفہوم یہ بنے گا کہ میں اس وقت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ سورج غروب ہوجائے اور سخت تاریکی چھا جائے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں فرماتا ہے.يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا.( الاحزاب:۴۶،۴۷) اے نبی ہم نے تجھے لوگوں کے لئے نمونہ او رایمان لانے والوں کے لئے ترقیات کی خوشخبری دینے والا اور منکرین کے لئے عذاب کی خبر دینے والا بنا کر بھیجا ہے.نیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور دنیا کو روشن کردینے والا سورج بنایا ہے.ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکنے والا سورج قرار دیاگیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیاکو منور کرے گا.پس سورۃ الفلق میں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے الفاظ کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم ساری دنیا میں پھیل جائے اور آپ وسط آسمان میں سورج کی طرح چمک کر ساری دنیا کو منور کر دیں.پھر اس کے بعد وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کہہ کر یہ ہدایت کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے کہ اس کے بعد کوئی ایسا وقت نہ آجائے کہ آپ کا روشن چہرہ دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور لوگ آپ کی روشنی سے محروم ہوجائیں اور دنیا پر تاریکی چھا جائے.اسی طرح اُمتِ مسلمہ کے ہر فرد کو حکم دیا کہ وہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کمال انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دینے والا ہے اور جو روحانی اور جسمانی ترقیات مسلمانوں کو دی جانے والی ہیں ان کے بعد ان پر زوال نہ آجائے اور ایسانہ ہو کہ وہ کسی وقت قرآنی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور قرآن کریم کے نور سے محروم ہوجائیں.اور ان پر تاریکی چھاجائے اور اسی طرح مادی ترقیات ملنے کے بعد کوئی
Page 432
ایسا سبب پیدا نہ ہو جس سے وہ تباہی کے گڑھوں میںجاگریں.اور اگر کوئی ایسی بات مسلمانوں کی غلطیوں کی وجہ سے پیدا ہوجائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی خود دستگیری فرمائے اور ایسے حالات پیدا کردے کہ پھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ دنیا دیکھنے لگے اور تنزّل کے دن ترقی سے بدل جائیں.(۲) غَسَقَ کے ایک معنے کسی چیز کی کثرت کے ہیں.چنانچہ کہتے ہیں غَسَقَتِ السَّمَآءُ غَسْقاً اَیْ اِنْصَبَّتْ وَاَرَشَّتْ کہ بادلوںمیں اتنا پانی تھا کہ وہ زور سے بہہ پڑے اوراسی طرح آنکھ جب آنسوئوں سے ڈبڈبا آئے اور خودبخود آنسو بہنے لگیں تو اس وقت بھی غَسَقَ کا لفظ استعمال کیا جاتاہے.پس ان معنے کے اعتبار سے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کے معنے ہوں گے کہ آسودگی کے بعد تنگی سے میں پناہ چاہتا ہوں.یہ ظاہر ہے کہ کبھی دولت کی زیادتی خراب کرتی ہے اور کبھی دولت کی کمی.جیسے کبھی نور کی زیادتی کی وجہ سے آنکھیں ماری جاتی ہیں اور کبھی تاریکی کی وجہ سے آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں.سورج کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے والا بھی اپنی آنکھیں کھو بیٹھتا ہے اور اندھیرے میں رہنے والوں کی بھی آنکھیں ماری جاتی ہیں جب تک درمیانی راہ اختیا رنہ کی جائے چین و آرام حاصل نہیں ہوسکتا پس مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں تو مال کی زیادتی اور اس کے نقصان سے بچنے کے لئے دعا سکھائی اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں مال کی کمی کے نقصانات سے محفوظ رہنے کی طرف اشارہ کیا.کیونکہ یہ حالت بھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ کَادَ الْفَقْرُ اَنْ یَّکُوْنَ کُفْراً(الجامع الصغیر حرف الکاف).یعنی مال کی کمی بعض اوقات انسان کے ایمان کو ضائع کردیتی ہے.پس اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا سکھائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے التجا کرو کہ مال ملنے کے بعد پھر فقر کی نوبت نہ آئے.کیونکہ جو شخص شروع سے غریب ہو اس کو غربت کا احساس زیادہ نہیں ہوتا.لیکن جب کوئی شخص امارت کے بعد تنگی کے دن دیکھتا ہے تو اس کے دن گذرنے مشکل ہوجاتے ہیں.پس ایسی حالت سے بچے رہنے کی دعا کے لئے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ کے الفاظ سکھائے گئے ہیں.(۳) غَاسِقٌ کے معنے سورج کے بھی ہیں اور چاند کے بھی.اور وقوب کے معنے گرہن لگنے کے بھی ہیں.پس وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کے معنے ہوں گے.میں اس وقت کے شر سے پناہ چاہتاہوں جبکہ سورج اور چاند کو گرہن لگے.سورج اور چاند کو گرہن لگنے کے دومعنے ہیں :.الف.یعنی وہ انوار جو خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ترقیات کے لئے ضروری ہیں، مٹ جائیں اور جو چیزیں اس نور کو مکتسب کرتی ہیں وہ بھی اس نور کو حاصل نہ کرسکیں جیسے سورج کی ذاتی روشنی ہے اور چاند اس سے روشنی حاصل کر
Page 433
کے دنیا کو منور کرتا ہے.اگر ایسے حالات پیدا ہوجائیں کہ چاند سورج سے روشنی حاصل نہ کرسکے اور تاریک ہوجائے تویہ حالت بھی وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کے ماتحت آئے گی.پس وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں گو دعا سکھائی گئی ہے.لیکن اس میں یہ پیشگوئی ہے کہ ایک زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہوجائے گا اور نہ صرف یہ کہ آپ کا نور عوام الناس نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ آپ کے نور کو اپنے اندر جذب کر کے اسے دنیا میں پھیلانے والے صلحاء اور اولیاء جو قمر کا درجہ رکھتے ہیں وہ بھی موجود نہیں ہوں گے اور تاریکی ہی تاریکی چھا جائے گی.پس ایسے وقت میں جو شر اُمت مسلمہ کو پہنچ سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے.باء.ظاہری لحاظ سے یہ بھی مراد ہوسکتی ہے کہ اس آیت میں سورج اور چاند کو گرہن لگنے کی طرف اشارہ ہے اور بتایا ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے تو اس کے شرور سے پناہ چاہو.احادیث میں یہ بات پوری وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ اُمت محمدیہ پر روحانی اور جسمانی ترقیات کے بعد ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب کہ وہ تنزّل کے گڑھے میں گرجائے گی اور اسلام کا صرف نام ان میں باقی رہ جائے گا اور قرآن کریم صرف اوراق میں ہوگا لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا(مشکوٰۃ کتاب العلم ).ہر قسم کی خرابی ان میں پھیل جائے گی اور ان کی وہ حکومتیں اور شان وشوکت جو قرآن کریم کی بدولت ان کو ملی تھیں ختم ہوجائیں گی.ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اُمت محمدیہ کی دستگیری فرمائے گا اور ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو مسیح او رمہدی کا نام پائے گا اور اس کے ذریعہ اسلام ہر حیثیت سے غالب ہوجائے گا اور اس کی مٹی ہوئی عظمت پھر سے قائم ہو جائے گی.مہدی اور مسیح کے مبعوث ہونے کے وقت کئی نشانات ظاہر ہوں گے اوران میں سے ایک نشان سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگنے کا بھی ہے.چنانچہ فرمایا اِنَّ لِمَھْدِیِّنَا اٰیَتَیْنِ لَمْ تَکُوْنَا مُنْذُ خَلَقَ اللہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ یَنْکَسِفُ الْقَمَرُ لِاَوَّلِ لَیْلَۃٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَتَنْکَسِفُ الشَّمْسُ فِی النِّصْفِ مِنْہُ.(دار قطنی کتاب العیدین باب صفۃ الکسوف و الـخسوف) یعنی جب ہمارا مہدی دین اسلام کی عظمت کو قائم کرنے کے لئے مبعوث ہوگا تو اس وقت اس کے دعویٰ کے ثبوت کے لئے دونشان ظاہر ہوں گے اور یہ نشان کسی مدعی کی صداقت کے لئے مقرر نہیں کئے گئے.پہلا نشان تو یہ ہے کہ چاند کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں رمضان کے مہینہ میں پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا اور اسی مہینہ میں سورج کو اس کی گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ کو گرہن لگے گا.
Page 434
اس حدیث میں سورج اور چاند گرہن کے متعلق ایک خاص پیشگوئی کی گئی ہے.پس مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں اس بات کے لئے دعا سکھائی گئی ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے کہ اسلام کمزوری کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ مہدی اور مسیح کو دین اسلام کی عظمت قائم کرنے کے لئے کھڑا کرے تو اس زمانہ کے شرور سے اللہ تعالیٰ بچائے اور اس کے اعوان و مددگار وں سے بنائے اور اس کے مخالف لوگوں پر جو عذاب آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے.(۴) جیسا کہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کی تفسیر میں لکھا جاچکا ہے.ان آیات میں ان کمزوریوں سے بھی پناہ کی دعا سکھائی گئی ہے جو خَلقی طور پر رہ جاتی ہیں.اور کمال کے حصول میں روک بن جاتی ہیں.ان آیات کے بعد مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں انجام کی خرابی سے بچنے کے لئے دعا سکھائی.کیونکہ کبھی ابتدا تو اچھی ہوتی ہے لیکن انتہا خراب ہوجاتی ہے.بعض اوقات ایسی بے موقعہ اور بے محل انتہا ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ نیکی قائم رہے بربادی ہوجاتی ہے.اسی وجہ سے اس آیت میں انسانی زندگی کی درمیانی حالت کو چھوڑ کر انتہا کو لے لیا یعنی مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں ابتدا کو لیا اور اس کے بعد درمیانی حالت کو بیان نہیں فرمایا بلکہ انتہا کو لے لیا اور فرمایا وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کہ وہ ڈوبنے والی اور آنکھوں سے اوجھل ہونے والی چیز جو گڑھے میں چلی جاتی ہے یعنی جبکہ انسان مرجاتا ہے زمین میںدفن ہوجاتا ہے.اس وقت کے بدنتائج سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس طرح پیدائشی کمزوریوں سے جو میرے لئے روک ہو سکتی تھیں پناہ مانگتا ہوں.اسی طرح اس سے بھی پناہ مانگتاہوں کہ ایسی حالت نہ پیداہوجائے کہ میرے مرنے سے ایسے نقائص پیدا ہوجائیں جن سے دین کو نقصان پہنچے یا میرے کام ادھورے رہ جائیں اور ان کا انجام اچھا ہونے کی بجائے برا ہو جائے.دنیا میں موتیں بھی بدیوں کا باعث ہو جاتی ہیں.انسان ایک کام پور انہیں کرنے پاتا کہ مرجاتا ہے.بعد میں اس کام سے کوئی نیک نتیجہ نکلنے کی بجائے برے نتائج نکلنے لگتے ہیں.اس لئے فرمایا دعا کرو کہ مرنے والوں کے ساتھ جو بدیاں تعلق رکھتی ہیں یعنی مرنے کے بعد جو پیدا ہو سکتی ہیں ان سے بھی بچائے.یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاموں کو پورا کرے گا اور میرا انجام نہایت خوش کن ہوگا.چنانچہ ۱۹۴۲ء میں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہاماً فرمایا :.مَوْتُ حَسَنٍ مَوْتٌ حَسَنٌ فِیْ وَقْتٍ حَسَنٍ کہ حسن کی موت بہترین موت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی جو بہتر ہوگا.اس الہام میں مجھے حسن رضی اللہ عنہ کا بروز کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کو پورا کرے گا.اور میرا انجام بہترین انجام ہوگا اور جماعت میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہ ہوگی.فالحمد للہ علی ذالک.
Page 435
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کی تشریح کرتے ہوئے بتایاگیا ہے کہ فلق کے متعدد معنے ہیں.اس کے معنے جہنم کے بھی ہیں اس کے معنے لکڑی کے بھی ہیں جس میں قیدیوں کو جکڑا جاتا ہے اور اس کے معنے اس دودھ کے بھی ہیں جو پیالہ میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے.ان معنوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ وہ ان حالات سے پناہ مانگیں کہ جن سے قوم یا افراد جہنم میں جاپڑیں.اسی طرح وہ ان اسباب سے محفوظ رہنے کی دعا مانگیں جن سے قید خانوں کا منہ دیکھنا پڑے.یا وہ اس بات سے پناہ مانگیں کہ ان سے قرآنی تعلیم اٹھ جائے اور ان کے پاس اس کا بہت تھوڑا سا حصہ رہ جائے.پس یہ ساری حالتیں تنزّل کی ہیں اور تاریکی کے مشابہ ہیں.ان سب حالتوں سے بچنے کے لئے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں جامع دعا سکھائی گئی ہے اور بتایا گیاہے کہ اُمت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چین و آرام کے بعد جھگڑوں میں پڑنے اور حکومت کے بعد ماتحتی کی ذلّت سے بچائے اور ایسے حالات سے محفوظ رکھے جن کی وجہ سے تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے.قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کی تفسیر میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس میں قومی دعا کے علاوہ فردی طور پر بھی کمال تک پہنچنے کے لئے دعا سکھائی گئی ہے.ان معنوں کے اعتبار سے مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کا یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بعد جب ترقیات کا راستہ ملتا او رنور کا مینار روشن دکھائی دیتا ہے اس وقت اگر اندھیرا ہوجائے تو وہ پہلی حالت سے بھی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے جیسے انسان جب روشنی سے یکلخت اندھیرے میں آجائے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا.روحانی مراحل طے کرتے ہوئے اس قسم کی حالتیں مومن پر آتی رہتی ہیں.قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبض اور بسط دونوں حالتیں مختلف اوقات میں مومن پر طاری ہوتی ہیں.بعض دفعہ اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ہے.یہ بسط والی حالت ہوتی ہے.دوسری حالت میں اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو نور اسے نظر آیا تھا وہ غائب ہوگیا.کئی نادان ایسی حالت میں مایوس ہوجاتے ہیں اور عین کامیابی کے سرے پر پہنچ کر ناکام رہتے ہیں.وہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ انہیں نظر آیاوہ شاید نور نہیں تھا.خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کہ اے مسلم !تم دعا کرو کہ اے خدا جب تیرا نور حاصل ہوجائے تو قبض کی حالت میرے لئے روحانی موت کا موجب نہ ہوجائے بلکہ موجب ترقی ہو اور کمال کو دیکھنے کے بعد میں زوال کو نہ دیکھوں اور حسرت کی موت سے نہ مروں.وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کے حکم کے مطابق جب کامل توحید کو ماننے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے کسی کی پروا نہیں.تو اس وقت مخالفت شروع ہوجاتی ہے اور دوست
Page 436
دوستیاں چھوڑ دیتے ہیں.اور ہمدرد بھی مخالف ہوجاتے ہیں گویا ایک قسم کی ظلمت چھا جاتی ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتاہے.فرمایا ایسے وقت میں مَیں اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ چاہتاہوں.اسی طرح سے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں کمال کے حصول کے لئے دعا سکھائی گئی تھی.اس کے بعدوَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کا اس مضمون کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ ایسا شخص یہ التجاء کرتا ہے کہ کمال کے حصول کے دوران میںان چیزوں کے بدا ثر سے میری ذات کو بچا جو غفلت کی حالت میں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں او ربے خبری میں اچانک مجھ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں.اس جگہ یہ سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلمت اور تاریکی آنی ہی تھی تو پھر دعائوں کی کیا ضرورت تھی.سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان دعائوں سے بے شک ساری قوم کلیۃً فائدہ نہ اٹھا سکی.لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کی دعائوں سے بیج کو ہر زمانے میںمحفوظ رکھا اور ایسی چنگاری باقی رہتی چلی گئی جس سے ہرزمانے میں دوبارہ آگ روشن کی جاسکتی تھی.پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس لئے دعائیں کرائیں کہ مسلمانوںکی ترقیات کے زمانہ میں اُمت کا جو حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت رکھتاہو آپ کی دعائوں کے طفیل بچ جائے اور آپؐسارے زمانوں کے لئے شفیع ہوسکیں چونکہ اس شر کا تعلق جس کے پھیلنے کی پیشگوئی مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کے الفاظ میں کی گئی تھی ساری امت سے تھا اس لئے پہلی صدی میں بھی جن لوگوں نے اپنی مناسبت کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں سے حصہ پایا وہ گویا آپ کی شفاعت سے نجات پاگئے.اور اس طرح آپ ان کے لئے بھی شفیع ہوئے.اسی طرح دوسری تیسری یا بعد کی صدیوں میں جولوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت کی وجہ سے اس دعا کے باعث روحانی شرور سے بچ گئے وہ آپ کی شفاعت کے مستحق ہوگئے.او ر اس طرح ہر دور میں ایسے لاکھوں انسان جن کی دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں سے مل گئیں وہ بچ گئے او رباوجود اس کے کہ شر ترقی کرتا گیا اور وہ تاریکی کا زمانہ آگیا جو مقدر تھا اور اس نے محمدی نور کو ڈھانپ لیا اور اسلام سے مسلمانوں کا تعلق نام کا رہ گیا.اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوگئی جس میں آپؐنے فرمایا تھا کہ لَایَبْقٰی مِنَ الْاِسْلَامِ اِلَّا اسْـمُہٗ وَلَا یَبْقٰی مِنَ الْقُراٰنِ اِلَّا رَسْـمُہٗ.(مشکوٰۃ کتاب العلم ) کہ ایک زمانہ میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور اس پر عمل نہیں ہوگا اور اسی طرح قرآن کریم صرف تحریر میں باقی رہ جائے گا اور اس کے احکام پر عمل چھوڑ دیا جائے گا.پس ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائوں کی بدولت اسلام کو بچانے کے لئے ایک فارسی الاصل انسان کو کھڑا کر دیا.جو قرآن کو پھر آسمان سے زمین پر لایا اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کی راتیں روشن دنوں میں
Page 437
تبدیل ہوگئیں.پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ضائع نہیں ہوئیں اور نہ امت محمدیہ کے افراد کی دعائیں رائیگاں گئیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دعائوں کی وجہ سے ہی فیصلہ کیا کہ آسمانِ اسلام پر ایک ایسا چاند طلوع کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اسی طرح سے دکھادے گا جس طرح چودہویں کا چاند سورج کو دکھاتا ہے.پھر یہ امر بھی یادر کھنا چاہیے کہ معوّذتین کے بعد قرآن کریم ختم نہیں ہوجاتا بلکہ جیسا کہ مسلمانوں میں دستور ہے قرآن کریم کے خاتمہ کے بعد پھر شروع کی آیات پڑھی جاتی ہیں تا کہ تسلسل قائم ہوجائے اوریہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ سے شروع ہوتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ترقی کے بعد زوال ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہر رات کے بعد دن نکلے.اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اَعُوْذُ کے بعد دوبارہ سورج چڑھتا ہے پہلے انبیاء کا سورج جب غروب ہوا تو پھر نئی اُمت قائم کی گئی ہے مگر قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اَعُوْذُ کے طفیل دوبارہ پھر حمدآجاتی ہے اور وہی سلسلہ شروع ہوجاتا ہے گویا اس میں بتایا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنے والا پھر ترقی کرے گا.پھر یہ تمام دور اس پر گذریں گے اور پھر محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اَعُوْذُ آڑے آئے گا اور پھر فلق محمدی شروع ہوگا.یہ د۲و اَعُوْذُ جو قرآن کریم کے آخر میں رکھے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ محمدی ختم نہ ہوگا.پس یہ حکمت تھی آخر میں اَعُوْذُ رکھنے کی.باقی کتابوں کے شروع میں اَعُوْذُ تھا اس لئے وہ ختم ہوگئیں.لیکن قرآن کریم کے شروع میں بھی اَعُوْذُ پڑھنے کا حکم ہے اور آخر میں بھی اَعُوْذُ نازل کردیا گیا ہے اور ہر فرد امت کو اس کے پڑھنے کا حکم ہے.گویا یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم نہ ہوگا بلکہ برابر چلتا رہے گا.وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِۙ۰۰۵ اور (تمام ) ایسے نفوس کی شرارت سے (بچنے کے لئے بھی ) جو (باہمی تعلقات کی) گِرہ میں (تعلق تڑوانے کی نیت سے ) پھونکیں مارتے ہیں.حلّ لُغات.اَلنَّفَّاثَاتُ: اَلنَّفَّاثَۃُ کی جمع ہے جو نَفَثَ سے مبالغہ کا مؤنث کاصیغہ ہے اور نَفَثَ مِنْ فِیْہِ کے معنے ہیں رَمٰی بِہٖ.یعنی کسی چیز کو منہ سے پھینکا اور جب نَفَثَ الْـجُرْحُ الدَّمَ کہیں تو معنے ہوں گے اَظْھَرَہٗ.زخم سے خون نکل آیا.نیز نَفَثَ کے معنے ہیں بَزَقَ وَقِیْلَ بَزَقَ وَلَا رِیْقَ مَعَہٗ اَوْ ھُوَ کَا لنَّفْخِ وَاَقَلُّ
Page 438
مِنَ التَّفْلِ.یعنی اس نے تھوکا اور بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ نَفَثَ کا لفظ اس طور پر تھوکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ منہ سے آواز تو نکلے لیکن تھوک نہ نکلے یا جیسے منہ سے پھونک ماری جاتی ہے اور آواز نکلتی ہے ویسے آواز نکلے اور نَفَثَ فُلَانًا کے معنے ہیں سَـحَرَہٗ اس نے اس پر جادو کیا اور جب نَفَثَتِ الْـحَیَّۃُ السَّمَ کہیں تو معنے ہوتے ہیں نَکَزَتْ.سانپ نے زہر نکالااور نَفَثَ الْقَلَمُ کے معنے ہیں کَتَبَ قلم نے لکھا اور نَفَثَ اللہُ الشَّیْءَ فِی الْقَلْبِ کے معنے ہوتے ہیں اَلْقَاہُ.اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کوئی بات القاء کی.(اقرب) پس نَفَّثٰت کے معنے ہوں گے.بہت تھوکنے والے گروہ یا نفوس (۲) زہر اُگلنے والے گروہ یا نفوس.(۳) دلوں میں وسوسے ڈالنے والے گروہ یا نفوس.(۴) بہت لکھنے والے گروہ یا نفوس.اَلْعُقَدُ :اَلْعُقْدَۃُ کی جمع ہے اور اَلْعُقْدَۃُ کے معنے ہوتے ہیں اَلْوِلَایَۃُ عَلَی الْبَلَدِ.یعنی کسی شہرپر حکومت.نیز اَلْعُقْدَۃُ کے معنے ہیں اَلضَّیْعَۃُ.جاگیر.اَلْعِقَارُ الَّذِیْ اِعْتَقَدَ ہٗ صَاحِبُہٗ مِلْکاً اَیْ اِقْتَنَاہُ.وہ جائیداد جس کوکوئی شخص اپنی ملکیت خیال کرتا ہے نیز عقدہ کے معنے ہیں مَوْضِعُ الْعَقْدِ گرہ لگانے کی جگہ.اسی طرح اَلْعُقْدَۃُ کے معنے ہیں مَا یُـمْسِکُ الشَّیْءَ وَیُوْثِقُہٗ گرہ.اَلْبَیْعَۃُ الْمَعْقُوْدَۃُ لِلْوُلَاۃِ وہ بیعت جو حکمرانوں کے ہاتھ پر کی جاتی ہے اس کو بھی عقدہ کہتے ہیں.اَلْمَکَانُ الْکَثِیرُ الشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَالْکَلَأِ الْکَافِیْ لِلْاِبِلِ.اس جگہ کو بھی عقدہ کہتے ہیں جہاں پر کثرت سے درخت، گھاس اور پانی ہو جو اونٹوں اور دیگر جانوروں کے لئے کافی ہو.وَمَا فِیْہِ بَلَاغُ الرَّجُلِ وَ کِفَایَتُہٗ.وہ چیز جس پر انسان کا سہارا ہو نیز اَلْعُقْدَۃُ کے معنے ہیں کُلُّ اَرْضٍ مُـخْضَبَۃٍ.سرسبز زمین.وَالْعُقْدَۃُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ وُجُوْبُہٗ وَاِحْکَامُہٗ وَاِبْرَامُہٗ اور ہر چیز کی عقدہ اس کو کہیں گے جس کو پورا کرنا اور پختہ رکھنا ضروری ہو.(اقرب) مفردات میں ہے اَلْعَقْدُ.اَلْـجَمْعُ بَیْنَ اَطْرَافِ الشَّیْ ءِ.کہ عقدکے معنے دو چیزوں کی اطراف کو اکٹھا کرکے باندھنے کے ہیں لیکن کبھی یہ لفظ مجازاً استعمال ہوتا ہے مثلاً ہر اس عہد اور امر کو عقد کہیں گے جس کی خلاف ورزی نہ کی جاسکتی ہویا جس کو کالعدم قرار نہ دیا جا سکتا ہے.پس وَمِنْ شَـرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ کے معنے ہوں گے (۱) میں پناہ چاہتاہوں ان نفوس کے شر سے جو دوستیوں اور معاہدات کو تڑوا دیں.(۲) میں پناہ چاہتاہوں ان گروہوں کے شر سے جو خلفاء کا مقابلہ کروائیں اور ان کی بیعت تڑوادیں.(۳) میں پناہ چاہتاہوں ان نفوس کے شر سے جو اتحاد کو برباد کرائیں اور مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ کرائیں.
Page 439
تفسیر.جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ اَلْعَقْدُ کے معنے ہیں اَلْوِلَایَۃُ عَلَی الْبَلَدِ یعنی حکومت یا گورنری.او راسی طرح سے اس کے معنے اَلْبَیْعَۃُ لِلْوُلَاۃِ کے بھی ہیں.یعنی حکام اور خلفاء کی بیعت.اور نَفْثٌ فِی الْعُقَدِ ایک محاورہ ہے جس کے معنے تعلقات قطع کروانے کے ہیں.اہل عرب میں یہ قاعدہ تھا کہ انقطاع تعلقات کے وقت گرہیں کھول کھول کر پھونک مارتے تھے.آج کل بھی جادو کرنے والے لوگ جدائی ڈلوانے کے لئے اس طرح کرتے ہیں.عربی میں کہتے ہیں فُلَانٌ یَنْفُثُ فِی الْعُقَدِ یعنی فلاں شخص تعلقات محبت منقطع کراتا ہے.پس وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرنی چاہیے جو تعلقات بیعت کو تڑوادیں اور مسلمانوں کے اتحاد میں رخنہ پیدا کردیں.آیت زیر تفسیر سے پہلی آیات میں مسلمانوں کے تنزّل کی پیشگوئی کی گئی تھی.اب اس آیت میں وجوہات تنزل میں سے ایک وجہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اُمت محمدیہ کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کے لئے خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا جس کی وجہ سے بہت سی برکات حاصل ہوں گی.لیکن مسلمانوں پر کچھ عرصہ بعد ایسا وقت آجائے گا جبکہ ان کی خلافت سے وابستگی کچھ عرصہ بعدختم ہوجائے گی اور ان کے اندر لامرکزیت پیدا ہوجائے گی.راعی اور رعایا کے تعلقات منقطع ہوجائیں گے اور اس کا باعث یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مفتوحہ ممالک میںسے ہر ایک ملک میں ایسے گروہ پیدا ہو ں گے جو اسلام کے دشمن ہوں گے اور نہایت ہوشیاری سے کام کریں گے اور ایسے خیالات پھیلائیں گے جن کی وجہ سے کمزور مسلمانوں کے دلوں میں خلفاء کے خلاف بعض خیالات پیدا ہوجائیں گے اور آخر ان کے تعلقات خلفاء سے ختم ہوجائیں گے.حتی کہ خلفاء پر حملے ہوں گے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیداہوجائے گا اور خلافت سے وابستگی ختم ہو کر لامرکزیت پیداہوجائے گی اور مسلمانوں کا دن تاریک رات سے بدل جائے گا.ترقیات رُک جائیں گی وہ آپس میں لڑ بھڑ کر جہنم پیدا کر لیں گے اور روحانیت اور پاکیزگی ختم ہوجائے گی.کیونکہ وہ جڑیں جن سے یہ برکات حاصل ہوتی ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہی ٹوٹ جائے گا.پس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی ہے کہ ان کو ایسے وقت کے شرور سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے.حل لغات میں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے نَفَثَ کے معنے لکھنے کے بھی ہیں اس لحاظ سے نَفّٰثٰت کے ایک معنے لکھنے والے نفوس یا گروہوں کے بھی ہوں گے.گویا ان معنوں کے اعتبار سے مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں بڑی کثرت سے ایسا لٹریچر شائع کیا جائے گا جو خدا اور اس کے رسول
Page 440
کے خلاف ہوگا اور جس کی وجہ سے دنیا میں بڑا بھاری شر اور فتنہ پیدا ہوجائے گا اس فتنہ سے بچنے کے لئے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ آخری زمانہ جس میں بڑی کثرت سے خدا تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لٹریچر شائع کیا جائے گا.اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں بچائے او رہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے.ضمنی طور پر اس سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ آخری زمانہ میں ایسا لٹریچر شائع کیا جائے گا جس میں حکو مت اور رعایا کے تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی.(۲) جیسا کہ آیات مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے.ان آیات میں ان کمزوریوں سے بچنے کی بھی دعا سکھائی گئی ہے جو خَلقی طور پر انسان میں ہوتی ہیں.تا وہ کمال کے حصول میں مانع نہ بن جائیں اور ان خرابیوں سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے جو بے وقت موت سے پیدا ہوجاتی ہیں.ابتدائی اور انتہائی خرابیوں سے پناہ کی دعا سکھانے کے بعد وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ میں زندگی کے درمیانی عرصہ میں جو خرابیاں پیش آجایا کرتی ہیں.ان سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور بتایاگیا ہے کہ بعض اوقات پیدائش میں بھی کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہوتی اور بے موقع موت بھی نہیں ہوتی.ہاں درمیانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں اوران کے بھی دو حصے ہوتے ہیں.(۱) وہ حصہ جو پیدائش کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے (۲) وہ حصہ جو موت کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.پہلے حصہ کے متعلق فرمایا وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ یعنی انسان کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں سے ایسے ہی خوراک لیتا ہے جیسے پودا جڑسے لیتا ہے.گویا ربوبیت کے لحاظ سے اس کا ماں باپ سے ظاہر ی تعلق ہوتا ہے اور باطنی لحاظ سے خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے یعنی وہ روحانی طور پر خدا تعالیٰ کا فرزند ہوتاہے کیونکہ خدا تعالیٰ ہی اسے پیدا کرتا ، خدا تعالیٰ ہی اس کی ربوبیت کرتا اور اسے بڑھاتا ہے.آیت زیر تفسیر میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے انسان کا تعلق اور عقد ایسا ہے کہ تمام قوتیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں اور نشو ونما پاتی ہیں.مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شریر لوگ خیالات میں وسوسے ڈال کر بندہ کو خدا تعالیٰ سے علیحدہ کروادیتے ہیں او رنالائق بندہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے جس طرح دنیا میں نالائق بچے ماں باپ کو چھوڑدیتے ہیں اور ان سے قطع تعلق کرلیتے ہیں.اس لئے خدا تعالیٰ نے دعا سکھلائی کہ کہو ایسا نہ ہو کہ وہ گرہ جس سے ہم خدا تعالیٰ سے فیوض حاصل کرتے ہیں وہ ٹوٹ جائے.بلکہ ایسا ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلقِ روحانی اب ہونے کے لحاظ سے ہے وہ گرہ مضبوط رہے.تاایسا نہ ہو کہ جو غذا مجھے وہاں سے ملتی ہے وہ بند ہوجائے اور میں ہلاک ہوجائوں.الغرض مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں خلقی کمزوریوں سے بچنے کی دعا سکھائی اور مِنْ شَرِّ
Page 441
(۲) جیسا کہ آیات مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے.ان آیات میں ان کمزوریوں سے بچنے کی بھی دعا سکھائی گئی ہے جو خَلقی طور پر انسان میں ہوتی ہیں.تا وہ کمال کے حصول میں مانع نہ بن جائیں اور ان خرابیوں سے بھی پناہ طلب کی گئی ہے جو بے وقت موت سے پیدا ہوجاتی ہیں.ابتدائی اور انتہائی خرابیوں سے پناہ کی دعا سکھانے کے بعد وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ میں زندگی کے درمیانی عرصہ میں جو خرابیاں پیش آجایا کرتی ہیں.ان سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور بتایاگیا ہے کہ بعض اوقات پیدائش میں بھی کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہوتی اور بے موقع موت بھی نہیں ہوتی.ہاں درمیانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں اوران کے بھی دو حصے ہوتے ہیں.(۱) وہ حصہ جو پیدائش کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے (۲) وہ حصہ جو موت کے زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.پہلے حصہ کے متعلق فرمایا وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ یعنی انسان کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں سے ایسے ہی خوراک لیتا ہے جیسے پودا جڑسے لیتا ہے.گویا ربوبیت کے لحاظ سے اس کا ماں باپ سے ظاہر ی تعلق ہوتا ہے اور باطنی لحاظ سے خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے یعنی وہ روحانی طور پر خدا تعالیٰ کا فرزند ہوتاہے کیونکہ خدا تعالیٰ ہی اسے پیدا کرتا ، خدا تعالیٰ ہی اس کی ربوبیت کرتا اور اسے بڑھاتا ہے.آیت زیر تفسیر میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے انسان کا تعلق اور عقد ایسا ہے کہ تمام قوتیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں اور نشو ونما پاتی ہیں.مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض شریر لوگ خیالات میں وسوسے ڈال کر بندہ کو خدا تعالیٰ سے علیحدہ کروادیتے ہیں او رنالائق بندہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے جس طرح دنیا میں نالائق بچے ماں باپ کو چھوڑدیتے ہیں اور ان سے قطع تعلق کرلیتے ہیں.اس لئے خدا تعالیٰ نے دعا سکھلائی کہ کہو ایسا نہ ہو کہ وہ گرہ جس سے ہم خدا تعالیٰ سے فیوض حاصل کرتے ہیں وہ ٹوٹ جائے.بلکہ ایسا ہو کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلقِ روحانی اب ہونے کے لحاظ سے ہے وہ گرہ مضبوط رہے.تاایسا نہ ہو کہ جو غذا مجھے وہاں سے ملتی ہے وہ بند ہوجائے اور میں ہلاک ہوجائوں.الغرض مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ میں خلقی کمزوریوں سے بچنے کی دعا سکھائی اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں موت کے ساتھ تعلق رکھنے والی خرابیوں اور مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ میں زندگی میں پیش آنے والی ان باتوں سے جن سے دور ہوکر انسان کمال سے محروم ہوجاتا ہے اور کمال حاصل کرنے کی طاقتیں کمزور پڑجاتی ہیں.(۳) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں ایک مسلمان کو یہ ہدایت تھی کہ اگر وہ کامل توحید پر ایمان لایا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہر جگہ پر کرنا چاہیے اور اگر اس وجہ سے مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑے ہوں اور ہر طرف تاریکی چھا جائے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے.بلکہ ان مخالفتوں کے باوجود توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہیے.وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ میں یہ بتایاگیا ہے کہ کامل توحید کو ماننے والا جب یہ اعلان کرے گا کہ اب میں نے خدا سے تعلق قائم کر لیا ہے تو کچھ دوست قائم رہیں گے اور کہیں گے تم نے بڑا اچھا کام کیا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیا.مگر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ان حمایت کرنے والوں کو بدظن کرنے کی کوشش کریںگے اور چاہیں گے کہ دوست بھی دشمن بن جائیں.پس ایسے وقت کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے توحید کو ماننے والے تم یہ اعلان کردینا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتاہوں ان لوگوں کے شر سے جو میرے دوستوں کے دلوں میں وساوس پیدا کررہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ تعلقات محبت توڑ کر میرے دشمن ہوجائیں اور میرے راستہ میں مشکلات پیدا کریں.(۴) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ میں کمال کے حاصل کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بھی دعا کرو کہ کمال کے بعد تم پر زوال نہ آئے اور مصائب کامنہ نہ دیکھنا پڑے.اس کے بعد فرمایا وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ.ایسے وقت میں جب انسان مشکلات و مصائب میں مبتلا ہو کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوجاتے ہیں جو گرے ہوئے کو گراتے اور اسے اور زیادہ ذلیل اور رسوا کرنے کے درپے ہوجاتے ہیں اور جس وقت انسان مشکلات میں مبتلا ہو اس وقت بعض لوگ اس کے رہے سہے تعلقات بھی بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں.او راسے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ یہ عام طورپر مشاہدہ میں آتا رہتا ہے کہ گھر میں ذرا کسی بچہ پر ناراض ہوں تو دوسرے بچے جھٹ اس کے متعلق شکایتیں کرنے لگ جاتے ہیں کوئی کہتا ہے اماں جان اس نے فلاں موقع پر یہ شرارت کی تھی.کوئی کہتا ہے اباجان اس نے یہ بھی شرارت کی تھی.غرض جب کوئی گرجائے اور ذلیل ہوجائے تو جھٹ اس کی اور لوگ شکایتیں کرنے والے کھڑے ہوجاتے ہیں.پس ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ لوگ جو تعلقات میں رخنہ ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی
Page 442
پناہ چاہو.کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہوتو انسان کے تعلقات اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں اور رشتہ داروں اور حکمرانوں سے قائم رہ سکتے ہیں.کیونکہ انسان کو کچھ علم نہیں کہ کس طرف سے وسوسہ اندازی ہو کر یہ تعلقات ختم ہوجائیں اور ان میں رخنہ پڑجائے.وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَؒ۰۰۶ اور ہر حاسد کی شرارت سے (بھی ) جب وہ حسد پر تُل جاتاہے.حلّ لُغات.حَاسِدٌ.حَسَدَ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے.اور حَسَدَ عَلَیْہِ حَسْدًا کے معنے ہوتے ہیں تَـمَنّٰی زَوَالَ نِعْمَتِہٖ اِلَیْہِ کہ اس نے یہ خواہش کی کہ فلاں کو جو نعمت ملی ہو اس سے چھن کر اس کو حاصل ہوجائے.(اقرب) پس حَاسِدٌ کے معنے ہوں گے وہ شخص جو دوسرے کی نعمت کو دیکھ نہیں سکتا اور چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چھن جائے اور اس کو مل جائے.تفسیر.وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ میں تنزل کے اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر کیا گیا تھا اور بتایا گیاتھا کہ اگر قومی شیرازہ بکھر جائے اور لامرکزیت آجائے تو قوم تباہ ہوجاتی ہے.اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ایسے حالات سے بچائے اور اگر ایسے حالات کبھی پیداہوں تو ان کے بدنتائج سے محفوظ رکھے.اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قومی تباہی کا ایک اور سبب بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ بعض اوقات کوئی قوم اس وجہ سے تباہ ہوجاتی ہے کہ کوئی بیرونی دشمن اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو نعمتیں مال کی فراوانی اور آرام و آسائش اس قوم کو حاصل ہوتی ہیں وہ اس سے چھین لے اور خود ان سے فائدہ اٹھائے.اگر ایسا دشمن ملک پر حملہ کرنے کے بعد غالب آجائے تو پھر ماتحت ملک کی ترقی ختم ہوجاتی ہے اور اس کی جنّت جہنم سے تبدیل ہوجاتی ہے اور اسے مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے.پس وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ کے الفاظ کہہ کر دعا سکھائی کہ اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں غلبہ دینا ہے اور جس کے نتیجہ میں تمہاری ترقی کا سورج وسط آسمان میں چمکے گا اور تمہارا ملک جنت بن جائے گا تم اس غلبہ کے متعلق دعا کرو کہ کوئی حاسد حملہ کر کے اس نعمت کو تم سے چھین نہ لے.
Page 443
الغرض اس سورۃ میں نہایت لطیف رنگ میں مسلمانوں کے غلبہ کی بشارت دی اور پھر مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ تنزّل او راس کے اسباب کو مدّ ِنظر رکھیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے.اس مضمون کو ادا کرتے ہوئے مسلمانوں پر جس جس رنگ میں تباہی آنی تھی اس کا بھی ذکر کر دیا.تاکہ مسلمان وقت پر متنبہ ہوسکیں.(۳) پھر سورۃ الفلق میں یہ مضمون بھی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل توحید پر ایمان لانے والے کو صرف خدا تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اس کی توحید کا ڈنکا ہر جگہ بجانا چاہیے اور اگر اس وجہ سے مخالفت کا طوفان اٹھے یا ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوں جو عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں اور بیوی بچوں کو اکسا کر خلاف کردیں.تب بھی اسے کسی کی پروانہیں کرنی چاہیے اس مضمون کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ کسی کی پرواہ نہ کرے تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ حقیقۃً خدا تعالیٰ کا ہوگیا.اوروہ اپنے دعویٔ توکل میں سچا تھا.اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جائے گا تو اس کی اس ترقی کو دیکھ کر اس کے حاسد بھی پیداہوجائیں گے جو طرح طرح کے طعنے دیں گے.کوئی کہے گا کہ اتفاقاً ترقی کر گیا.کوئی کچھ کہے گا اور کوئی کچھ.ایسے وقت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ اعلان کردو کہ مجھے اس وقت ایسے حاسدوں کی بھی کوئی پروا نہیں.میں اس وقت بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اسی کی پناہ میں آتاہوں کیونکہ وہ نہایت مہربان ہے اور اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا.پھر سورۃ کی ابتدائی آیات میں رَبِّ الْفَلَقِ کے الفاظ استعمال کر کے کمال کے حصول کے لئے دعا سکھائی گئی تھی اور پھریہ بتایاگیا تھا کہ یہ دعا کرو کہ جب کمال حاصل ہوجائے تو زوال کا وقت نہ آئے.اس کے بعد مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ.وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ کہہ کر بتایا ہے کہ انسان کی دوہی حالتیں ہوتی ہیں.یا ترقی یا تنزّل.تنزّل کے وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان کمزور ہوجاتا ہے تو کئی لوگ ایسے کھڑے ہوجاتے ہیں جو اسے اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ترقی ہو تو حسد کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں.غرض انسان کمزوری کی حالت میں ہو تو اسے اور زیادہ کچلنے والے آموجود ہوتے ہیں اور اگر بڑابن جائے تو حسد کرنے لگ جاتے ہیں.پس کوئی حالت ایسی نہیں جس میں انسان لوگوں کے شر سے محفوظ رہ سکے.اسے کمزوری میں بھی خطرہ ہے اور ترقی میں بھی خطرہ ہے.کمزوری کے وقت میں اسے ان لوگوں سے خطرہ ہے جنہیں اس بات میں مزہ آتا ہے کہ وہ گرے کو گرائیں اور مرے کو ماریں اور ترقی کے وقت اسے ان لوگوں سے خطرہ ہے جو حسد کرنے اور اسے نقصان پہنچانے
Page 444
کے درپے رہتے ہیں غرض کسی حالت میں بھی انسان مامون نہیں.اوروہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں.وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ میں ایک وجود کے مبعوث ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے جس کا نام احادیث میںمہدی اور مسیح رکھا گیا ہے اور بتایاگیا ہے کہ وہ ایسے وقت میں آئے گا جبکہ مسلمانوں کے اندر سخت تفرقہ ہوگا اور ان کا اتحاد باقی نہ رہے گا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جس شخص کو دنیا کی اصلاح کے لئے کھڑا کرے گا لوگ اس کی شدید مخالفت کریں گے اور اس پر حسد کریں گے.پس وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ایسے شخص کو مبعوث کرے تو اس کے حاسدوں میں سے نہ بنیں بلکہ اس کے معاونین و انصار میں سے ہو کر خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ہوں.وہ مضامین جو اس سورۃ کے خلاصۃً بیان کئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتاہے کہ یہ سورۃ اپنے مضمون کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور اُمت مسلمہ کو بحیثیت قوم اور افرا دکے ایک کامل دعا اس سورۃ کے ذریعہ سے سکھائی گئی ہے اور وہ اسباب جو قومی یا فردی طور پر تباہی کے پیدا ہوسکتے ہیں ان کو بیان کیاگیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب تک خدا تعالیٰ کی حفاظت میں نہ آئے اس دنیا میں خطرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا.پس امن کا صحیح راستہ یہی ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر جھکا رہے اور اس کی حفاظت طلب کرے.
Page 445
تاریخوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا تھا کہ جو نبی پہلے آئے اس پر رمضان کی پہلی تاریخوں میں کلام اتارا جائے اور بعد میں آنے والوں پر بعد میں اتارا جائے.اگر یہ بات ہے تو حضرت نوحؑ اور دیگر انبیاء جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں ان پر کس ماہ اور کس تاریخ میں کلام اترا.کیونکہ حضرت ابراہیم ؑ پر پہلی رمضان کو کلام اترا تھا پس حضرت نوحؑ کے لئے کوئی رات رمضان میں کلام اترنے کی باقی نہیں رہتی.اگر تو آگے پیچھے کلام اتر سکتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ان پر پہلی کے بعد کی کسی تاریخ میںکلام اترا ہو گا.لیکن حدیث بتاتی ہے کہ تقدم زمانی کے مطابق رمضان کی تاریخوں میںکلام اتارا گیا ہے پس حضرت نوحؑ چونکہ حضرت ابراہیم ؑ سے پہلے گذرے ہیں اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جس رات کو کلام اترا اس سے پہلے کسی رات میں ان پر کلام اترنا چاہیے تھا مگر پہلی رات سے پہلے تو اور کوئی رات ہوتی نہیں پس اگر رمضان ہی میں کلام اترنا چاہیے تو حضرت نوحؑ کے لئے کوئی جگہ انبیاء کی صف میں باقی نہیں رہتی.کہا جا سکتا ہے کہ اس جگہ شارع نبیوں کا ذکر ہے اور حضرت نوحؑ شارع نبی نہ تھے مگر یہ جواب نقل و کلام الٰہی دونوں کے خلاف ہے.تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ دائود اور نہ حضرت عیسٰیؑ شریعت لانے والے تھے.ان کی کتب جیسی بھلی بری بھی موجود ہیں ان میں دیکھ لو شریعت کا نام و نشان نہیں.حضرت دائود ؑ کی زبور میں تو صرف عشقِ الٰہی کا اظہار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ہیں اور کچھ اپنے اور اپنے متعلقین کے لئے دعائیں ہیں.شریعت سے ان کو دور کاواسطہ بھی نہیں.حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کا بھی یہی حال ہے.اس میں صرف حضرت عیسیٰ کی زندگی کے حالات ہیں اور کچھ معجزات کا ذکر ہے باقی اس امر پر زور ہے کہ موسٰی کی شریعت پر عمل کرو.اگر دائودؑ کوئی نئی شریعت لائے تھے یا حضرت عیسٰیؑ کوئی نئی شریعت لائے تھے تو موسٰی کی کتاب کو منسوخ قرار دینا پڑے گا.اس صورت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نہ تھے تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ دائودؑ کی کتاب پر عمل کرو اور اگر وہ صاحب شریعت تھے تو انہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ میری شریعت پر عمل کرو مگر انجیل تو شریعت سے اس قدر خالی تھی اور ہے کہ یہود کے اعتراض سے بچنے کے لئے حضرت مسیحؑ کے حواریوں کو یہ اعلان کئے بغیر چارہ نہ ہوا کہ شریعت لعنت ہے (گلتیوں باب ۳ آیت ۱۳)کیونکہ اگر وہ اسے رحمت قرار دیتے تو یہود کے اس سوال کا کیا جواب دیتے کہ مسیحؑ کی شریعت کہاں ہے کیونکہ وہ نصاریٰ کے زعم میں پہلے نبیوں سے بڑا تھا اور اس وجہ سے اسے دوسروں کی شریعت کا ناسخ بھی ہونا چاہیے تھا.قرآن کریم کی رو سے اس دعویٰ پر یہ اعتراض آتا ہے کہ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد
Page 446
پرورش سے نہیں ہوتا، بیل یا گھوڑے کی پرورش سے نہیں ہوتا بلکہ ابو جہل کی پرورش سے ہوتا ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ کا مقابلہ کیا.فرعون کی پرورش سے ہوتاہے جو خدا تعالیٰ کو گالیاں دیتا تھا.بے شک انسان بھی نیک سلوک کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت دشمن پر بھی ظاہر ہوتی ہے.جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.كُلًّا نُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءِ وَ هٰۤؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ.(بنی اسـرآءیل:۲۱ ) یعنی ہم مومن او رکافر سب کی مدد کرتے چلے جاتے ہیں وَ مَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا.(بنی اسـرآءیل:۲۱ ) اور تیرے رب کی عطاء کسی فرقے اور قوم سے روکی نہیں گئی.پس رحمانیت کا مظہر کامل انسان ہی ہے.دیکھو ابوجہل نے کس طرح مخالفت کی مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی اس سے سلوک کرتا گیا.فرعون کس قدر مخالفت کرتاتھا مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا نزول اس پر ہوتا تھا.زندگی کا زمانہ تو الگ رہا ابوجہل اور فرعون کی مرتے وقت کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی.فرعون نے مرتے وقت ایمان کا اظہار کیا اور بالفاظ دیگر اپنی نجات کے لئے دعا کی.اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا تقاضا تھا کہ یہ دعا قبول نہ ہو مگر رحمانیت اس کی قبولیت کی متقاضی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں.ابوجہل نے دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سچا ہے تو ہم پر پتھر برسا اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اچھا پتھر برسادو.تواللہ تعالیٰ نے ان کے مرتے وقت کی دعائیں بھی قبول کیں.چاہے بےوقوفی سے انہوں نے ایسے وقت میں دعائیں کیں کہ وہ ان سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے.پتھر برسنے کے بعد بھلا ابوجہل کو کیا فائدہ ہو سکتا تھا اور بدن کو نجات ملنے سے فرعون کو کیافائدہ ہوا؟ تو درحقیقت رحمانیت ایک لحاظ سے تو تمام مخلوق پر ظاہر ہوتی ہے.مگر ایک لحاظ سے انسان پر ہی اس کا اظہار ہوتا ہے.بےشک جانور اور کیڑوں مکوڑوں پر بھی رحمانیت کا اظہار ہوتاہے مگر حقیقی اظہار رحمانیت کا اس وقت ہوتاہے جب ایک انسان خدا کو گالیاں دے رہاہوتاہے.مگر اس وقت بھی اس کی زبان کو اللہ تعالیٰ خون بھیج رہا ہوتاہے.پس رحمانیت کا مظہر کامل انسان ہے.مَلِکِ النَّاسِ کی آیت صفت رحیمیت پر دلالت کرتی ہے لمبا او رمتواتر انعام دینا بادشاہ کا ہی کام ہے.مغلوں کی دی ہوئی جاگیریں آج بھی لوگ کھا رہے ہیں.بلکہ مغل تو قریب کے زمانہ میں ہی ہوئے ہیں.پٹھانوں کی دی ہوئی جاگیریں بھی آج تک لوگ کھا رہے ہیں.یہ بھی قریب کا زمانہ ہے ہندوستان میں ایسے جاگیر دار بھی ہیں جن کو ہندو راجائوں نے جاگیریں دی تھیں.اور جاگیر دار پندرہ پندرہ سو اور دو دو ہزار سال سے ان جاگیروں کو کھارہے ہیں.پس رحیمیت ملکیت کا ہی نظارہ ہے.حضرت دائود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا.اب بوڑھا ہوا پر میں نے صادق کو ترک کئے ہوئے اور
Page 447
دن میں نازل نہیں ہوا بلکہ تیئیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہواہے حتی کہ کفار نے اعتراض کیا کہ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً١ۛۚ كَذٰلِكَ١ۛۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا (الفرقان:۳۳) یعنی کفار کہتے ہیں کہ قرآن اس پر یک دم کیوں نازل نہ ہوا.جو اعتراض وہ کرتے ہیں درست ہے واقعہ میں وہ یک دم نازل نہیں ہوا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اتار کر تیرے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے (تا پہلے حصہ کی پیشگوئیاں پوری ہو کر دوسرے حصہ میں ا س کی طرف اشارہ ہو اور ایمان کی تقویت کی ایک دائمی بنیاد رکھ دی جائے ) اور ہم نے اس کی ترتیب نہایت اعلیٰ درجہ کی بنائی ہے یعنی نزول قرآن اس رنگ میں ہوا ہے کہ موجودہ وقت کے مومنوں کے ذہن نشین قرآن ہو جائے اور موجودہ وقت کے کافروں کے لئے بہترین طریقہ تبلیغ کا پیدا ہو اور بعد کی دائمی ترتیب ہم نے اور طرح رکھی ہے تا کہ وہ بعد میںآنے والوں کی ضرورت کے مطابق ہو.غرض نزول و ترتیب قرآن نہایت اہم حکمتوں پر مبنی ہے اور اس وجہ سے اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمانہ کی ضرورت کے مطابق اترنا نہایت اہم حکمتوں پر مبنی تھا اب اس آیت کی موجودگی اور تاریخ کی گواہی کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ سارا قرآن ایک رات میںاترآیا تھا.پہلے نبیوں کے متعلق بھی یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ ایک رات میں ان پر کلا م اترا تھا حضرت ابراہیم ؑ کی تاریخ تو ہمارے سامنے نہیں اس لئے ان کے بارہ میں تو ہم کچھ کہہ نہیںسکتے حضرت موسٰی، دائودؑ اور حضرت مسیحؑ کی تاریخ تو ہمارے سامنے ہے ان کی کتب کو دیکھ کر کوئی شخص شبہ بھی نہیںکر سکتا کہ وہ ایک وقت میں نازل ہوئی تھیں.حضرت موسیٰ کی کتب چالیس پچاس سال میںجا کر مدوّن ہوئی ہیں.ان میںراستوں سفروں ، مقاموں اور لڑائیوں کا بالترتیب ذکر ہے.حتی کہ یہ بھی ذکر ہے کہ کس طرح موسٰی نے اپنی قوم کی تنظیم کی اور کس طرح وہ جوانی سے ادھیڑ عمر کے ہوئے اور کس طرح بوڑھے ہوئے اور کھڑے ہو کر کام کرنے کے ناقابل ہو گئے.کیا اس مضمون کو ایک رات کا اترا ہوا مضمون کہا جا سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح اناجیل کا مضمون ہے اس میں بھی حضرت عیسیٰ ؑ کے دوروں ، لیکچروں، نشانوں ، خدا کی ہدایتوں کا ترتیب وار ذکر ہے اور کوئی شخص انہیں ایک دن کی اتری ہوئی کتاب نہیں کہہ سکتا.حضرت دائودؑ کی زبور بھی اسی طرح ہے کہیں اس میںدشمن فوج کے نرغہ میں گھر جانے کا ذکر ہے اور پھر اس سے نجات پانے کا.کبھی بیمار پڑجانے کا اور پھر اس سے صحت پانے کا.کبھی دشمنوں کی شرارتوں کا ذکر آتاہے اور پھر ان کے غم سے نجات پانے کا.غرض دائود کی زبور اس کی زندگی کے اتار چڑھائو کی ایک تاریخ ہے اور ا س کی زندگی کے حالات اس سے منعکس ہوتے ہیں پھر اسے ایک دن کا کلام کس طرح کہا جا سکتا ہے؟
Page 448
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور ) باربار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں ) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ۰۰۲ (ہم ہر زمانہ کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ ) تُو (دوسرے لوگوں سے ) کہتا چلاجا کہ میں تمام انسانوں کے رب سے (اس کی پناہ ) طلب کرتا ہوں.مَلِكِ النَّاسِۙ۰۰۳ (وہ رب جو) تمام انسانوں کا بادشاہ (بھی) ہے.اِلٰهِ النَّاسِۙ۰۰۴ (اور ) تمام انسانوں کا معبود (بھی ) ہے.تفسیر.سورۂ لہب کی تفسیر میں بتایا جا چکا ہے کہ اس میں ایک ایسی قوم کے خروج کا ذکر ہے جس نے آخری زمانہ میں اسلام پر حملہ کرنا تھا اور یہ کوشش کرنی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ختم ہوجائے.سورۃ الفلق کی آخری آیت وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ میں بھی اسی قوم کے حملوں سے بچنے کی دعا اُمتِ محمدیہ کو سکھائی گئی تھی.اور بتایا تھا کہ آخری زمانہ میں ایک طاقتور حاسد پیدا ہوگا جو اس بات کا متمنی ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اسلامی حکومتوں کو ختم کر کے اسلامی ممالک پر قبضہ کر لے.بلکہ اس کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ اسلام کا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہ رہے.چونکہ اس قوم کو مادی طور پر ہر قسم کی طاقتیں حاصل ہونی تھیں اور مسلمان بوجہ ضعف وکمزوری کے اس قوم کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہنے تھے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دعا سکھائی کہ اس خطرناک فتنہ سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو تا وہ ایسے اسباب پیدا کردے کہ اسلام نہ صرف اس دشمن کے حملوں سے محفوظ رہے بلکہ ضعف کے بعد اس پر پھر اس کی شان و شوکت کے دن آجائیں.سورۃ الناس کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے ذریعہ سے پناہ مانگو.چنانچہ فرمایا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.مَلِکِ النَّاسِ.اِلٰہِ النَّاسِ یعنی یہ کہو کہ اے خدا جو رب ہے لوگوں کا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں.اے
Page 449
آہستہ آہستہ نازل ہونے کے تو یہ معنے ہیں کہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذباللہ من ذالک ) نئے اور بدلنے والے حالات کے مطابق اور نئی ضرورتوں کے پیش آنے پر ایک نیا کلام بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں.چونکہ ان کے اعتراض کی بنیاد عقلی تھی اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ پہلے نبیوں پر کلام اکٹھا نازل ہو جاتا تھا اور فرض کرو کہ کفار مکہ ایسا کہتے بھی تھے تو کیا ان کے خیال کو ہم کوئی بھی اہمیت اور قیمت دے سکتے ہیں.کیا وہ علوم آسمانی کے ماہر تھے یا مذہبی تاریخ کا علم ان کو حاصل تھا کہ ہم ان کے اعتراض کو تاریخ مذہب کے لئے کوئی قیمت دیں؟ اس غلطی کے پیدا ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم میںحضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت آتا ہے کہ انہیں چالیس راتوں کے وعدہ میںالواح ملی تھیں(الاعراف:۱۴۳).مسلمان مفسرین چونکہ اسرائیلی کتب سے واقف نہ تھے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ الواح اور تورات ایک شے ہیں.حالانکہ الواح صرف دس احکام کا نام ہے اور تورات ان احکام سے سینکڑوں گنے زیادہ امور پر مشتمل ہے.قرآن کریم میں کسی جگہ بھی یہ ذکر نہیں کہ طُور پر موسٰی کو مکمل تورات ملی تھی.صرف الواح کا ذکر آتا ہے اور تورات بھی اسی کی مصدق ہے سو اوّل تو طُور پر جو کچھ نازل ہوا یک دم نازل نہیں ہوا چالیس راتوں میں نازل ہوا دوسرے وہاں جو کچھ نازل ہوا اس اندازہ کے مطابق وحی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی راتوں میں ہوئی ہے کئی کئی رکوع کا ٹکڑا آپ پر یک دم نازل ہو جایا کرتا تھا چنانچہ سورۂ یوسف کی نسبت آتا ہے کہ ساری سورۃ ایک ہی وقت میںنازل ہوئی تھی(فتح البیان زیر سورۃ یوسف).حضرت موسٰی پر جو کلام طُور پہاڑ پر چالیس دن میںنازل ہوا اس سے تو سورۂ یوسف یقیناً بڑی ہے.حضرت موسٰی کی وحی کے علاوہ دوسرے نبیوں کی وحی کی نسبت تو کوئی قوی یا ضعیف روایت بھی نہیں جس سے معلوم ہو کہ پہلے نبیوں پر کلام الٰہی یک دم نازل ہو جاتا تھا اور اگر ایسا لکھا بھی ہوتا تو ہم اسے خلاف عقل کہہ کر رد کر دیتے کیونکہ کلام الٰہی تو نبی اور خدا کے تعلق کو روشن کرتا رہتا ہے.کیا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ کسی نبی پر ایک رات میں سب کلام نازل کر کے خدا تعالیٰ خاموش ہو جائے گا کلام الٰہی تو الٰہی تعلق پر شہادت ہوتا ہے کیا اس شہادت کے پیدا ہو جانے سے نبی کی قلبی کیفیت اطمینان والی رہ سکتی ہے ؟ کیا وہ اس محجوب اور محبوب سے دور زندگی کو راحت سے گذار سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چند دن کے وحی کے وقفہ سے کیا حال ہوا تھا.اگر ایک دن کلام کر کے خدا تعالیٰ دوسرے نبیوں سے بقیہ ساری عمر خاموش رہتا تو میں سمجھتا ہوں دشمن تو ان کو مارنے میں ناکام رہتے لیکن یہ خدائی فعل ان کو مارنے میںضرور کامیاب ہو جاتا.خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا یا دوسری آیات جو اوپر لکھی گئی ہیںان کا ہرگز یہ
Page 450
اب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الناس میں سارا نقشہ مغربی اقوام کا کھینچا گیا ہے اور یہی وہ حاسد قوم ہے جس کو مسلمانوں کی طاقت دیکھنا گوارا نہیں.اور وہ چاہتی ہے کہ اسلام کا نام دنیا سے مٹ جائے.پس اس قوم کے پیدا کردہ فتنوں سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی ہے اور دعا کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ میں ربّ النّاس کی پناہ چاہتاہوں.صفتِ ربوبیت کے ماتحت تمام وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی ضروریات کہلاتی ہیں اور جن کو ملک کی اقتصادیات کے نام سے پکارا جاتا ہے.گویا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کا حاسد نکلے گاتو سب سے پہلے ان کی اقتصادیات کو تباہ کرے گا اور تجارت کو نقصان پہنچائے گا.وہ پہلے فوجوں سے حملہ نہیں کرے گا بلکہ پہلا کام اس کا یہ ہوگا کہ تجارتی سامان لے کر اسلامی ممالک میں جائے گا.وہاں بنک وغیرہ کھولے گا اور اقتصادیات پر قابض ہو جائے گا.چنانچہ یوروپین اقوام ہر جگہ ابتداء میں اسی طرح پہنچی ہیں.پہلے تجارت کا سامان لے کر گئے اور آہستہ آہستہ اقتصادیات پر قبضہ کر لیا.سود پر روپیہ دیا اور اس طرح اسلامی حکومتوں کو کمزور کرتے رہے.گویا اسلام نے جو ربوبیت کا نظام قائم کیا ہے.اسے اس نے توڑدیا.پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فتنے سے محفوظ رہنے کے لئے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کے الفاظ سکھائے اور بتایا کہ اگر ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا.رَبِّ النَّاسِ کے بعد مَلِکِ النَّاسِ کے الفاظ سکھائے.گویا اس میں یہ اشارہ کیا کہ مغربی اقوام کے اقتصادی فتنہ کے بعد ملوکیت کا فتنہ شروع ہوگا.چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اقوام پہلے تجارت کے ذریعہ سے ملکوں میں داخل ہوئیں اور پھر انہوں نے وہاں حکومتیں قائم کرلیں.مصر، افریقہ، ہندوستان وغیرہ سب اسلامی سلطنتوں کو انہوں نے اسی طرح قبضہ میںکیا.افریقہ میں پہلے پہل یہ لوگ کانچ کی چوڑیاں اور دانہ ہائے تسبیح لے کر گئے اور چونکہ یہ چمکدار چیزیں تھیں وہاں کے جاہل لوگ اسے قیمتی چیز سمجھ کر سونا اور ہیروں کے بدلے لیتے تھے اور آخر کار یہ لوگ وہاں قابض ہوگئے.اور اسی طرح ہندوستان، ایران، عرب، ٹرکی وغیرہ مقامات پر بھی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے اپنا اثرو نفوذ قائم کیا اور پھر دوسرا قدم یہ تھا کہ اپنی بادشاہتیں قائم کرلیں.اور اس طرح اسلام کے سیاسی تمدّن پر قابض ہوگئے.مَلِکِ النَّاسِ کے بعد اِلٰہِ النَّاسِ کے الفاظ رکھے گئے ہیں اور اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جب مغربی اقوام مختلف ممالک میں بادشاہتیں قائم کرلیں گی.توان کی طرف سے ایک اور فتنہ برپاہوگایعنی مذہبی پروپیگنڈا شروع کردیں گی.اور اس طرح مسلمانوں کا ایمان متزلزل کردیں گی.او رنیا فلسفہ او رنئی تعلیم پیش کر کے مذہب کو برباد کرنے کی کوشش کریں گی.کالجوں وغیرہ میں تعلیم کے ذریعہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو کھوکھلا کردیں گی اور اس قسم کا لٹریچر شائع کریں گی جس سے مذہب اسلام ایک غیر معقول مذہب نظر آئے اور لوگ اس سے متنفر ہوں.پس فرمایا اے مسلمانو !جب تمہیںان حالات سے دوچار ہونا پڑے تو تم اس خدا کی پناہ چاہو.جو رَبّ.مَلِک اور اِلٰہ ہے یعنی یہ دعاکرو کہ اے خدا صحیح ربوبیت، صحیح ملوکیت اور صحیح الوہیت جس کو تُو دنیا میں رائج کرنا چاہتا
Page 451
ہیں یا چند پیشگوئیاں ان میں مذکور ہیں).ان روایتوں میں پانچ کتابوں کا ذکر معلوم ہوتا ہے کہ غلط العام عقیدہ سے متاثر ہوئے بغیر یہ روایات نقل کی گئی ہیں اس لئے غالب احتمال یہ ہے کہ یہ احادیث درست ہیں ہاں ظاہر معنوں میں نہیں ہیں بلکہ مجاز و استعارہ کا استعمال ان میں کیا گیا ہے.یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیمؑ ، حضرت موسٰی ، حضرت دائودؑ، حضرت مسیحؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی خاندان کے درخشندہ ستارے ہیں اور گو ابراہیم موسوی سلسلہ سے پہلے اور حضرت نوحؑ کے تابع نبیوں میں سے تھے.موسٰی، دائود اور مسیحؑ اسرائیلی سلسلہ کے نبی تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمدی سلسلہ کے بانی تھے اور نبوت کے سلسلہ کے لحاظ سے یہ پانچوں نبی تین مختلف سلسلوں سے متعلق تھے مگر خاندان کے لحاظ سے یہ پانچوں نبی ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے.پس ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں کلام الٰہی کے سلسلہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ ابراہیمی خاندان کے لحاظ سے ایک حکمت بیان کی گئی ہو.اگر یہ درست ہے تو نہ حضرت نوحؑ کے ذکر کی اس حدیث میں ضرورت تھی اور نہ دوسری اقوام کے نبیوں کے ذکر کی ضرورت تھی.اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پانچ نبیوں کو رمضان میں الہام ہوا خواہ جُزْأً خواہ کُلًّا.تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس خیال کو اوپر تفصیل سے ردّ کر آیا ہوں.پس رمضان سے رمضان کا مہینہ مراد نہیں بلکہ مجازاً سلسلہء الہام کا نام رمضان رکھ دیا گیا ہے.رمضان رَمَضَ سے نکلا ہے اور رَمَضَ کے معنے عربی زبان میں شدید گرمی یا سورج کی شدید تپش کے ہوتے ہیں اور رَمَضَاءُ کے معنے اس میدان کے ہوتے ہیں جو گرمی کے موسم میں سورج کی براہ راست شعاعوں کی وجہ سے تپ اٹھا ہو.چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے ؎ اَلْمُسْتَجِیْـرُ بِعَمْرٍو عِنْدَ کُرْبَتِہٖ کَالْمُسْتَجِیْـرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ (اقرب) یعنی عمرو (اس کا مخالف) سے مصیبت کے وقت مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسا کہ شدید گرم میدان سے بچنے کے لئے کوئی آگ کی پناہ ڈھونڈے یعنی رَمَضَاء کی گرمی آگ کے قریب قریب ہوتی ہے.معلوم ہوتا ہے کہ جب رمضان نام اس مہینہ کا رکھا گیا ہے اس وقت یہ مہینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا ہوگا.بہرحال رمضان کے روزے تو اسلام میں فرض ہوئے اور اس مہینہ کا نام رمضان بہت پہلے رکھا گیا ہے.پس رکھنے والے نے یہ نام شدت گرما کی وجہ سے ہی رکھا ہوگا اور کلام الٰہی ہمیشہ اسی وقت آتا ہے جبکہ دنیا میں گناہ اور فسق وفجور کی وجہ سے لوگ غضب الٰہی کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمی نسل
Page 452
موجب بن جاتی ہے.اسی طرح اِلٰہِ النَّاسِ سے بھی تباہی آتی ہے.وہی مذہبی لیڈر اور راہنما جو بہتری کی ہزاروں تجاویز سوچتے اور لوگوں کی برتری کے لئے کوشاں رہتے ہیں.بسا اوقات جب ظاہرمیں لوگوں کی درستی کی تدابیر کررہے ہوتے ہیں باطن میں وہ انہیں تباہ کر رہے ہوتے ہیں.پنڈت، پادری اور دوسرے مذہبی راہنما اپنی اپنی قوم کو بیسیوں اچھی باتیں بتاتے اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں.جھوٹ نہ بولو، فریب نہ کرو، دھوکا نہ دو، قتل نہ کرو، خیانت نہ کرو، سچائی اور دیانتداری اختیار کرو.یہ سب باتیں دنیا کے تمام مذہبی پیشوا بتاتے ہیں لیکن جہاں وہ لوگوں کے ایک حصہ کو درست کرنے کی کوشش کررہے ہوتے ہیں وہیں وہ ان کے دوسرے حصہ کو تباہ بھی کر رہے ہوتے ہیں.جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو.جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم غریبوں کا بوجھ اٹھائو اور مسکین اور نیک دل بن جائو.جہاں امراء سے چندے لے کر غرباء کی امداد کے لئے خرچ کئے جاتے ہیں اور اس طرح نیک باتیں دنیا میں قائم کی جاتی ہیں.وہاں ساتھ ہی یہ کہہ کر کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے نیکی کی تمام تعمیر کو برباد کردیا جاتا ہے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.مَلِکِ النَّاسِ.اِلٰہِ النَّاسِ تو کہہ اے خدا دنیا میں بے شک ربوبیت کرنے والے ہیں.مگر ان کی ربوبیت دودھاری تلوار کی طرح ہوتی ہے.جو ایک طرف اگر تیرے دشمن کو کاٹتی ہے تو دوسری طرف میری گردن بھی اڑادیتی ہے.اے خدا دنیا کے بادشاہ ! میری جان، میرے مال، میری عزت اور میری آبرو کی حفاظت کرتے اور میری سہولت اور آرام کے لئے ہر قسم کی آسائشیں مہیا کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ ان کی مخفی کوشش مجھے تباہ کرسکتی ہے او رمجھے تنزل میں گرا سکتی ہے.اے خدا میرے لئے دنیا میں مذہبی پیشوا بھی ہیں جو ایک رنگ میں میرے لئے مطاع کی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ اپنے مذہبی پیشوائوں کو اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ سمجھتے ہیں اور وہ واقعہ میں بنی نوع انسان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دراصل کوئی مذہبی پیشوا ایسا نہیں ہوتا جو ترقی کی باتیں اپنی قوم کو نہ بتا تاہو.لوگ ایسے بے وقوف نہیں ہوتے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنا مذہبی لیڈر او رمذہبی پیشوا بنالیں.جو انہیں کوئی کام کی بات نہ بتائے.مگران مذہبی پیشوائوں کی طرف سے بھی شر پہنچ سکتا ہے اور یہ انسان کو تباہ کر سکتے ہیں.لیکن کون سا ایسا رب ہے جس کی طرف سے خیرہی خیر آتی ہے شر نہیں آتا.کون سا ایسا مَلِک ہے جس کی طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے شر نہیں آتا.کون سا ایسا اِلٰہ ہے جس کی طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے شر نہیں آتا.وہ صر ف خدا تعالیٰ ہی ہے.پس فرمایا تو کہہ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.مَلِکِ النَّاسِ.اِلٰہِ النَّاسِ.میں اپنے تمام اہلی تعلقات سے نظر اٹھا کر میں اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے ماں باپ
Page 453
اور اپنے دوسرے رشتہ داروں اور اپنی قوم سے نظر اٹھا کر اس خدا کی طرف آتا ہوں جو ربّ النّاس ہے.میں حکومتوں کے بغیر دنیا میں گذارہ نہیں کرسکتا مگر چونکہ مجھے ان کی طرف سے شر پہنچنے کا ہر وقت احتمال ہے اس لئے میں اس بادشاہ کی طرف اپنی نظر پھیرتا ہوں جس کے یہ سب اظلال ہیں.اور اس کی پناہ میں آتاہوں پھرمذہبی طور پر خدا تعالیٰ کے اظلال کہلانے والے بھی موجود ہیں جن کو بعض لوگوں نے اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ بنا لیا ہے.مجھے ان سے فائدے پہنچتے ہیں مگر مضرتوں کا بھی امکان ہے.اس لئے میں اس کی طرف نظر اٹھاتاہوں جس کی طرف سے خیر ہی خیر آتی ہے.اگر کوئی شخص اس سورۃ کے اس مفہوم کو مدّ نظر رکھ کر دعا کیا کرے تو نہ اسے اہلی خطرات پیش آئیں نہ بادشاہت کا کوئی فتنہ اسے نقصان پہنچائے نہ مذہبی پیشوائوں کی وجہ سے کوئی ضعف پہنچے.پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.مَلِکِ النَّاسِ.اِلٰہِ النَّاسِ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر حکومتیں تمہیں ڈرائیں.تمہاری بات نہ سنیں.تم پر ظلم کریں.تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تم میرے دربار میں آئو میں تمہارا اصل بادشاہ ہوں.اگر ملک یا قوم یا خاندان کی طرف سے تم پر ظلم کیا جاتا ہے تو تم میرے دربار میں آئو.میں تمہارا رب ہوں.اور تمہارا خاندان اور تمہاری قوم بھی میرے قبضہ میں ہے.اگر مذہبی پیشوا تمہیں گمراہ کرنا چاہیں تو تم میرے دربار میں آئو کیونکہ میں تمہارا اِلٰہ ہوں اور تمہاری ہدایت میرے ذمہ ہے اور اگر تم میرے پاس آئوگے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا.نہ ربوبیت کی قسم کا، نہ ملکیت کی قسم کا، نہ الوہیت کی قسم کا.جس طرح مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ کوئی تمہیں چھیڑے تو میرے پاس آجانا اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں دنیا میں بھیج رہاہوں تمہارے ارد گرد تمہارے بھائی بند ہوں گے.دوست، عزیز اور رشتہ دار ہوں گے.اہلِ قوم اور اہلِ ملک ہوں گے.اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ میرے پاس آنا.ان سے تمہیں خیر بھی پہنچ سکتا ہے اور شر بھی.لیکن اگر کبھی ان سے شر پہنچے تو تم میرے پاس آنا.اسی طرح دنیا میں نظام قائم رکھنے کے لئے حکومتیں ہوں گی ان سے تمہیں خیر بھی پہنچ سکتا ہے اور شربھی.لیکن اگر کبھی تمہیں ان سے شر پہنچے تو تم میرے پاس آئو.پھر دنیا میں روحانی پیشوا بھی ہیں.ہوسکتا ہے کہ وہ تمہاری تربیت تو کریں مگر ایسے رنگ میں کہ بجائے فائدہ کے تمہیں نقصان پہنچا دیں اور تمہاری روح کو کچل دیں.پس اگر یہ صورت ہو تو بھی تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے.تمہارااصل روحانی پیشوا میں ہوں تم میرے پاس آجانا.پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا.الغرض آخری زمانہ میں ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت کے ماتحت جو فتنے مخالفین اسلام کی طرف سے اٹھنے والے تھے ان کے لئے اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.مَلِکِ النَّاسِ.اِلٰہِ النَّاسِ میں ایک جامع دعا امت محمدیہ کو سکھادی گئی ہے.
Page 454
(۳) سورۃ الفلق کی تفسیر میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اس سورۃ میں دوسرے مضامین کے علاوہ پیدائش، موت اور زندگی کے زمانہ کی خرابیوں سے پناہ کی دعا سکھائی گئی ہے.اس کے مقابل پر سورۃ الناس میں خدا تعالیٰ کی تین صفات رب.ملک اور اِلٰہ کا ذکر کیا گیا ہے.جو انہی زمانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کا ذکر سورۃ الفلق میں کیا گیا ہے.پیدائش کی صفت کا تعلق رَبّ سے ہے.موت کی صفت کا تعلق مَلِک سے ہے.اور زندگی کی صفت کا تعلق اِلٰہ سے ہے.چنانچہ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ کے مقابلہ میں اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ رکھا اور مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ کے مقابلہ میں مَلِکِ النَّاسِ رکھااور مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِیْ الْعُقَدِ.وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ کے مقابلہ میں اِلٰہِ النَّاسِ رکھا ہے.یعنی تینوں حالتوں کے ساتھ تین صفات جو تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر سورۃ الناس میں کیا گیا ہے.پیدائش کے لحاظ سے انسان کا تعلق خدا تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے ہوتا ہے اور یہ حالت ہر وقت جاری رہتی ہے کیونکہ انسان کی پیدائش بھی ہروقت جاری رہتی ہے.انسان کھانا کھاتا ہے تو اس لئے کہ اس سے خون بنے اور اس کی زندگی کا ذریعہ ہو.اس سے معلوم ہوا کہ پیدائش ہر وقت جاری رہتی ہے گو نطفہ کے لحاظ سے پیدائش ہوچکی مگر حقیقتاً ہر وقت ہوتی رہتی ہے.حتی کہ ڈاکٹروں کاخیال ہے کہ سات سال تک انسان کا جسم بالکل بدل جاتا ہے تو پیدائش ہر وقت جاری رہتی ہے.اس لئے خدا تعالیٰ سے ربوبیت کا تعلق بھی ہر وقت جاری رہتا ہے اور جس طرح زمانہ خلق انسان کے لئے تھا اسی طرح ربوبیت کی کیفیت بھی اس میں پائی جاتی ہے اس لئے فرمایا قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہہ دے میں اس رب کی پناہ مانگتاہوں جس کی تمام انسانوں میں ربوبیت جاری ہے اور ہردم ایسے تغیرات انسان کے جسم میں ہورہے ہیں جو یا تو اسے بدی کی طرف لے جاتے ہیں یا نیکی کی طرف.میں اس تغیر کرنے والی صفت سے پناہ مانگتاہوں کہ وہ مجھے برائی کی طرف نہ لے جائے.بلکہ نیکی کی طرف لے جائے.پھر میں مَلِکِ النَّاسِ کی پناہ مانگتاہوں.موت بھی انسان پر ہر وقت جاری رہتی ہے.پیشاب، پاخانہ، پسینہ، ناخن، بال کیاہیں.جسم کے وہ اجزاء جو مردہ ہوجاتے ہیں یہ عارضی اور جزوی موت ہے جو انسان پر آتی رہتی ہے.پس موت بھی جاری رہتی ہے اس لئے مَلِکِ النَّاسِ کی پناہ مانگنے کے لئے کہا گیا کہ جزا سزا کی جو صفت جاری ہے اس کے متعلق پناہ مانگتاہوں.ایسا نہ ہو کہ ناکامی کا زمانہ آجائے بلکہ انعام ملتے رہیں اور خدا کے فضل ہوتے رہیں میں یہ چاہتاہوں کہ ان میں روک نہ واقع ہو.
Page 455
تیسری حالت یہ ہوتی ہے کہ خود غرضی داخل ہوجاتی ہے اور نیت خالص نہیں رہتی.اس کے لئے فرمایا کہو اِلٰہِ النَّاسِ میں اس خدا کی جو سب کا معبود ہے پناہ مانگتاہوں کہ میرے اپنے اندر کوئی فتور نہ پیدا ہواو ر اگر کبھی پیدا بھی ہو جائے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ مجھے وہ اپنی الوہیت سے نکل جانے دے.اس لئے اس صفت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اے خدا میرا تجھ سے تعلق قائم رہے اور کبھی منقطع نہ ہو.پس قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ.مَلِکِ النَّاسِ.اِلٰہِ النَّاسِ میں ان تینوں حالتوں کے متعلق پناہ مانگنے کی بھی دعا سکھائی گئی ہے.مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ١ۙ۬ الْخَنَّاسِ۪ۙ۰۰۵ (میں اس کی پناہ طلب کرتاہوں )ہر وسوسہ ڈالنے والے کی شرارت سے جو (ہر قسم کے وسوسے ڈال کر آپ ) پیچھے ہٹ جاتا ہے.الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ۰۰۶ (اور ) جو انسانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کردیتا ہے.مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِؒ۰۰۷ خواہ وہ (فتنہ پرداز ) مخفی رہنے والی ہستیوں میں سے ہو.خواہ عام انسانوں میں سے ہو.حلّ لُغات.اَلْوَسْوَاسُ.اَلْوَسْوَاسُ اِسْـمٌ مِّنْ وَسْوَسَ اِلَیْہِ الشَّیْطٰنُ.وَسْوَاس وَسْوَسَ فعل کا اسم ہے اور وَسْوَسَ اِلَیْہِ الشَّیْطٰنُ کے معنے ہوتے ہیں حَدَّ ثَہٗ بِـمَالَا نَفْعَ فِیْہِ وَلَا خَیْرَ کہ اس کو وہ بات بتلائی جس میں کوئی نفع اور بھلائی نہیں.گویا وَسْوَاس کے معنے ہوں گے وہ بات جس میں کوئی نفع اور بھلائی نہ ہو.نیز وَسْوَاس کے معنے ہیں اَلشَّیْطَانُ.شیطان ھَمْسُ الصَّائِدِ وَالْکِلَابِ شکاری جب شکار کے لئے نکلتا ہے تو وہ اونچی آواز نہیں نکالتا.بلکہ ایسی آواز نکالتا ہے جو بالکل نیچی ہو.اس آواز کو اور کتوں کی آواز کو وسواس کہتے ہیں.اَلْوَسْوَاسُ اَیْضاً مَرَضٌ یَـحْدُثُ مِنْ غَلَبَۃِ السَّوْدآءِ وَیَـخْتَلِطُ مَعَہٗ الذِّھْنُ.وسواس اس مرض کو بھی کہتے ہیں جو سوداوی مادہ کے بڑھ جانے سے ہوجاتی ہے او رجس سے ذہن میں پراگندہ خیالات آنے شروع ہوجاتے ہیں.وَیُقَالُ لِمَا یَـخْطُرُ بِالْقَلْبِ مِنْ شَـرٍّ وَّ لِمَا لَا خَیْرَ فِیْہِ.وَسْوَاسٌ اور جو دل میں برے خیالات
Page 456
آتے رہے ہیں جن میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ان کو بھی وسواس کہتے ہیں.(اقرب) اَلْـخَنَّاسُ.اَلْـخَنَّاسُ خَنَسَ سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور خَنَسَ عَنْہُ کے معنے ہیں رَجَعَ وَتَنَحّٰی.اس کے پاس سے لوٹ آیا اور الگ ہو گیا.نیز خَنَسَ کے معنے ہیں تَاَخَّرَ پیچھے ہٹ گیا.اِنْقَبَضَ کسی بات سے دل میں انقباض محسوس کیا اور اگر یہ لفظ کجھور کے لئے استعمال کریں او رکہیں خَنَسَ النَّخْلُ تو معنے ہوں گے تَاَخَّرَتْ عَنْ قُبُوْلِ التَّلْقِیْحِ فَلَمْ یُؤَثِّرْ فِیْـھَا وَلَمْ تَـحْمِلْ فِیْ تِلْکَ السَّنَۃِ.کھجور نے نر کے مادے کو قبول نہ کیا اور اس وجہ سے پھل دار نہ ہوئی.اور خَنَسَ الشَّیْءُ عَنْکَ کے معنے ہیں سَتَرَہٗ.اس نے کچھ چھپا کر رکھا اور جب خَنَسَ بَیْنَ اَصْـحَابِہٖ کہیں تو معنے ہوں گے اِسْتَخْفیٰ وہ اپنے دوستوں کے درمیان چھپ گیا.خَنَسَ بِفُلَانٍ کے معنے ہیں غَابَ بِہٖ.اس کو لے کر غائب ہوگیا.خَنَسَ الْقَوْلَ کے معنے ہیں اَسَاءَہٗ بات کو برا سمجھا اور خَنَسَ اِبْـھَامَہٗ کے معنے ہوں گے قَبَضَھَا اپنے انگوٹھے کو دہرا کیا(اقرب).پس خنّاس کے معنے ہوں گے.(۱) بہت علیحدہ رہنے والا.(۲) بہت پیچھے ہٹنے والا.(۳) اثرکو بالکل قبول نہ کرنے والا.(۴) بات کو بہت چھپانے والا.(۵) اپنے ساتھیوں میں چھپ جانے والا.اَلْـجِنَّۃُ.اَلْـجِنَّۃُ : جَـمَاعَۃُ الْـجِنِّ یعنی جنوں کے گروہ اور ان کی جماعت کو عربی میں جِنَّۃ کہتے ہیں.اَلْـجِنُّ: اَلْاِنْسُ کے مقابلے پر بولاجاتا ہے.اَلْـجِنُّ کا لفظ جَنَّ سے ہے اور مادہ کے اعتبار سے اس کے اندر پوشیدہ رہنے کے معنے پائے جاتے ہیں.چنانچہ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو رحم میں مخفی ہوتا ہے.اور جنان دل کو کہتے ہیں جو سینے میں مخفی ہوتا ہے.پس جِنّ کے معنے ہیں مخفی مخلوق.ہر وہ ہستی جو نظروں سے مخفی رہے اس کو عربی میں جِنّ کہیں گے (اقرب).اسی لحاظ سے جِنّ کا لفظ امراء پر بولا جاتا ہے کہ وہ اپنے مکانوں میں بند رہتے ہیں اور ان تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے.تفسیر.مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ.الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِالنَّاسِ.مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ کے معنے ہیں.میں اس وسوسہ اندازی کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتاہوں جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے یا پوشیدہ رہ کر چھوٹے اور بڑے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے.مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ کی آیت یا تو یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِالنَّاسِ کے ساتھ متعلق ہے.اور اس صورت میں معنے یہ ہوں گے کہ وسوسہ اندازی کرنے والا لوگوں کے دلوں میں وساوس پیدا کرتا ہے اور وہ نہ چھوٹوں کو چھوڑتا ہے اور نہ بڑوں کو.بلکہ ہر ایک کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے.
Page 457
اسی طرح مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ کی آیت مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ سے بھی متعلق ہو سکتی ہے اور اس صورت میں یہ معنے ہوں گے کہ میں وسوسہ اندازی کرنے والوں کے شر سے پناہ چاہتاہوں جو وسوسہ ڈال کرخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا پوشیدہ رہتے ہیں اور ایسی ہستیاں چھوٹے لوگوں میں سے بھی ہیں اور بڑوں میں سے بھی.ظاہر میں بھی نظر آتی ہیں اور پوشیدہ بھی ہیں.جیسا کہ حل لغات میں بتایا جاچکا ہے کہ جنّ کا لفظ اِنس کے مقابلہ پر بولا جاتا ہے اور جِنّ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر نظر نہیں آتے یعنی اپنے گھروں میں بند رہتے ہیں اوران کی ڈیوڑھیوں پرپہرے لگے رہتے ہیں.اور وہ عوام سے نہیں ملتے اور انس ان کو کہتے ہیں جن سے انسان آسانی سے مل سکتا ہے گویا جِنّ کے معنے ہوں گے بڑے لوگ اور انس کے معنے ہوں گے عوام الناس یا عوام الناس سے میل جول رکھنے والے لوگ.اس حکمت کے ماتحت عمررضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں حکم دے دیا تھا کہ کوئی گورنر اپنی ڈیوڑھی پر دربان مقرر نہ کرے.تاکہ لوگ آزادی سے اس تک پہنچ سکیں(تاریـخ الطبری سنۃ ۲۳ھـ ذکر بعض سیرہٖ) تااس کی انسانیت قائم رہے اور وہ افسر بن کر جنّ نہ بن جائے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخری زمانہ میں جب مغربی اقوام اسلام پر حملہ آور ہوں گی اور مسلمانوں کی اقتصادیات کو تباہ کریں گی اور ان کے ملکوں پرقبضہ کرلیںگی تو یہ سب کچھ دھوکہ اور مکاری سے ہوگا.اور ظاہر میں تو یہ کہیں گے کہ ہم تہذیب سکھانے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان ملکوں میں علوم کی ترویج ہو.لیکن ان کا منشاء لوگوں کے دلوں میں وساوس پیدا کرنا ہوگا تا کہ لوگ خدا اوراس کے رسول سے بدظن ہوجائیں.اسی طرح حکومت کریں گے اور ظاہر یہ کریں گے کہ ہم اہلِ ملک کے فائدہ کے لئے سب کچھ کررہے ہیں.لیکن ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ کسی طرح یہ لوگ اپنے مذہب سے متنفر ہوکر ان کی تہذیب اور ان کے دین کو اختیار کرلیں.اور وہ کسی ایک کو نہیں بلکہ ہر ایک کو متأثر کرنے کی کوشش کریں گے.خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا.اور ان کا حربہ اتنا کامیاب ہوگا کہ آخر مسلمان اس سے متاثر ہوں گے اور ان کا تمدن ختم ہوجائے گا.کئی شرارت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ شرارت کرنے کے بعد سامنے کھڑے رہتے ہیں مگر کئی شرارت کرکے ایسے مخفی ہوجاتے ہیں کہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا اور بعض پوشیدہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں.مغربی اقوام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ سیاسیات اور دوسرے امور میں ہمیشہ ایسا طرز عمل اختیا رکرتی ہیں کہ جس کا دوسروں کو علم بھی نہیں ہوتا.اور دوسرا ملک تباہ ہو جاتا ہے.اسی طرح مختلف کتابیں لکھتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم علم پھیلا رہے ہیں لیکن یا
Page 458
تو اسلام سے نفرت پھیلاتے ہیں اور یا دہریت.گویا اس طرح سے اپنے ملکوں میں بیٹھے دوسروں کو تباہ کرتے ہیں.وَسْوَاسٌ کے ایک معنے صَوْتُ الْـحُلِیِّ کے بھی ہیں یعنی اس آواز کے جو زیوروں کی جھنکار سے پیدا ہوتی ہے.اس لحاظ سے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ کے یہ معنے ہیں کہ آخری زمانہ میں مغربی اقوام روپیہ کی لالچیں اور حِرص دِلا دِلا کر لوگوں کو گمراہ کریں گے اورپھر ساتھ ہی وہ خنّاس بھی ہوں گی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کھلے بندوں دس ہزار روپیہ کسی کو اپنی ذاتی اغراض کے لئے دیں.بلکہ وہ اس طرح دیں گی کہ روپیہ بھی دوسرے کو پہنچ جائے اور خود بھی چھپی بیٹھی رہیں.ایسے حالات میں ہر مومن کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ الٰہی تو مجھے ان کے فتنہ اور شر سے بچا.پھر یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِالنَّاسِ.مِنَ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ میں بتایاکہ یہ اقوام بعض دفعہ بڑے آدمیوں کے ذریعہ اور بعض دفعہ عوام الناس کے ذریعہ میرے دل میں روپیہ کی محبت پیدا کریں گی.یا یہ اقوام اتنی دولت مند ہوں گی کہ اگر میں بڑا ہوجائوں تب بھی یہ مجھے لالچ دے سکیں گی اور اگر میں عوام میں شامل رہوں تب بھی مجھے لالچ دے سکیں گی.ان آیات میں یہ پیشگوئی بھی ہے کہ آخری زمانہ میں جو فتنے برپاہوں گے ان میں آرگنائزیشن ہوگی یعنی ایک انتظام کے ماتحت یہ فساد ہوں گے.لوگ فرداً فرداً اس میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اکسائیں گے اور اپنے ساتھ ملائیں گے جس کے دل میں کوئی خیال ہوگا وہ اکیلا اس کے مطابق کام نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملائے گا.آقا کی ملازمت ایک نوکر خود نہیں چھوڑے گا بلکہ دوسروں کو بھی کہے گا کہ تم بھی چھوڑ دو.اسی طرح آقا دوسرے آقائوں کو کہے گا کہ اگر میں کسی ملازم کو اپنے کارخانہ سے نکالوں تو تم بھی اسے ملازم نہ رکھنا.آقا اپنی الگ مجلس بنائیں گے اور نوکر الگ.اسی طرح حکمران لوگوں کی علیحدہ تنظیم ہوگی اور ماتحتوں کی الگ.اورہر تنظیم دوسرے ملک کی تنظیم کے ساتھ تعلق رکھے گی.اسی طرح مذہب کے خلاف جو فتنے ہوں گے وہاں بھی انجمنیں ہوں گی مثلاً یہ نہیں کہ کوئی دہریہ ہو تو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے.بلکہ ان کی بھی انجمنیں ہوں گی اور وہ علی الاعلان کہیںگے کہ خدا کا غلط عقیدہ لوگوں کے دلوں سے مٹانا ہمارا کام ہے.پہلے زمانہ میں دہریہ تھے.مگر وہ اپنے خیالات کو الگ الگ ظاہر کرتے تھے کوئی ان کی انجمن نہ تھی.نہ وہ اخباریں او رٹریکٹس شائع کرتے تھے.مگر اس زمانہ میں دنیا کے تمام ممالک میں ان کی انجمنیں پائی جاتی
Page 459
ہیں.پھر اسلام کے خلاف لڑنے والوں کی انجمنیں ہیں اور تو اور مولویوں کو دیکھو.جو کبھی اکٹھے نہیں ہوسکتے تھے ان کی بھی انجمنیں ہیں اور کانفرنسیں ہوتی ہیں.اسی طرح پادریوں کی انجمنیں ہیں اور وہ تنظیم کے ماتحت کام کرتے ہیں.الغرض یہ وہی پیشگوئی ہے جو سورۃ الناس کی آخری آیات میں بیا ن ہوئی ہے.جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اس سورۃ کے ابتدا میں خدا تعالیٰ کی تین صفات کا ذکر تھا جو انسانی تین حالتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں.یعنی پیدائش، زندگی اور موت کے ساتھ.اور یہ بتایا گیا تھا کہ تمہیں دعا کرنی چاہیے کہ ہرحالت میں تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ رہے اور کبھی منقطع نہ ہو.اب مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ میں ان وسوسوں کی طرف اشارہ کیا جو تینوں زمانوں کے متعلق پیداہو کر خدا تعالیٰ سے تعلق منقطع کرا سکتے ہیں مثلاً کبھی یہ خیال آسکتا ہے کہ پیدا کرنے والا ہی کوئی نہیں.کبھی یہ خیال آسکتا ہے کہ انسان کے پیدا کرنے کی کوئی غرض ہی نہیں.کبھی انسان کہتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو جزا و سزا دے.کبھی الوہیت کے متعلق وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے.اس طرح قسم قسم کے وساوس پیدا ہوکر خدا تعالیٰ سے تعلق منقطع ہوجا تا ہے.اس قسم کے وساوس مختلف وجوہات کی بنا پر پیدا ہوسکتے ہیں.کبھی مخفی ہستیوں سے کبھی بدروحوں سے.کبھی ایسی بیماریوں سے جن میں انسان مبتلا ہوکر شبہات اور شکوک کا شکار ہوجاتا ہے.کبھی ایسے مکانات اور جگہوں سے جہاں شبہات پیدا ہوتے ہیں.اسی طرح انسانوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں جو شبہات ڈالتے ہیں.پس ان سب امور سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ ہر وہ امر جو شبہات پیداکرنے کا موجب ہو سکتاہے.میں اس سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتاہوں.اور یہ چاہتاہوں کہ میرا خدا تعالیٰ کی ربوبیت، ملکیت اور الوہیت سے تعلق رہے.میری ابتدا بھی اچھی ہو، انتہا بھی اچھی ہو اور میری زندگی کی ہر تبدیلی بھی اچھی ہو.پس ان آیات میں ایک جامع دعا سکھائی گئی ہے.سورۃ الناس قرآن کریم کی آخری سورۃ ہے.اور جب انسان سارا قرآن کریم پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں گھمنڈ پیدا ہوسکتا ہے کہ اب تو میں نے سارا قرآن پڑھ لیا اور اب میں شیطان سے محفوظ ہوگیا ہوں اور کوئی ٹھوکر نہیں کھا سکتا اس قسم کے خیالات چونکہ تباہ کرنے کا موجب ہوسکتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخرمیں فرمایا کہ اے بندے جسے اب قرآن کریم پڑھنا اور اسے ختم کرنا نصیب ہواہے تو یہ نہ سمجھ کہ تو شیطان کے پنجہ سے محفوظ ہوگیا ہے.بالکل ممکن ہے کہ رب العالمین خدا کو دیکھ کر او راس کی صفت کا اپنے آپ کو مورد پا کر تُو ٹھوکر
Page 460
کھا جائے.خدا کے فضل ہر انسان پر ہر گھڑی نازل ہورہے ہیں.ایسا نہ ہو کہ جب قرآن پڑھ کر خدا کے فضلوں کی طرف تیری توجہ ہو اور اس وقت خدا کی ربوبیت تیرے لئے ظاہرہوتو تُو گھمنڈ میں آجائے.او راس طرح ٹھوکر کھا جائے یا درکھو کہ خدا رَبِّ النَّاسِ ہے اس کے فیوض معمولی سے معمولی انسان پر بھی ہورہے ہیں.تجھ پر اگر کوئی فضل نازل ہوتاہے تو اس وجہ سے کوئی گھمنڈ نہ کر اور ٹھوکر نہ کھا.بلکہ سمجھو کہ جب تیرے دل میں خدا کی برکت اور فیض حاصل کرنے کی تڑپ پیداہوئی تو خدا نے اپنی صفت ربوبیت کے ماتحت تجھ پر کچھ نازل کر دیا.ہوسکتا ہے کہ اس وقت تک تیرے اندر پوری پاکیزگی نہ پیدا ہوئی ہو.پس تجھے دعا کرنی چاہیے کہ میں اس خدا سے پناہ مانگتاہوں جوسب کا رب ہے اور کہتا ہوں اے خدا جب تومیری حالت ناقص ہونے کی وجہ سے مجھ پر ناقص نعمتیں نازل کرتا ہے اور اس طرح ہمیشہ کے لئے نیک انجام ہونا مشکل ہے اس لئے میں تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر حقیقی رحمتیں نازل فرما اور ہر قسم کی ٹھوکروں سے بچا.پھر بعض قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں تو اس وقت ان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نوکروں اور خادموں میں شامل ہوجاتے ہیں.گویا اتنی نیکی ان میںپیدا ہوجاتی ہے کہ جس طرح سرکاری افسر ہوتے ہیں.اسی طرح کا درجہ انہیں مل جاتا ہے ان کی عام حالت نہیں رہتی.اس وقت بھی ٹھوکر کا خطرہ ہوتا ہے.اس لئے فرمایا کہو مَلِکِ النَّاسِ اے خدا یہ بھی نہ ہو کہ جب مجھ پر تیرے ایسے فضل نازل ہوں جیسے افسروں پر بادشاہ کے ہوتے ہیں تو اس وقت میں یہ سمجھ لوں کہ میں بھی کچھ بن گیا ہوں اور اس طرح تجھ سے دور ہوجائوں.اس لئے میں تجھ سے ہی پناہ مانگتاہوں کہ تُو اپنی بادشاہت کوکار فرما کر اور میری اصلاح کر اور جس طرح تُو چاہتا ہے کہ تیری رعایا کے ساتھ سلوک کیا جائے اسی قسم کے سلوک کی مجھے توفیق بخش تا میں مغرور ہو کر ظالم اورمتمرّد نہ بن جائوں.پھر افسر اور بادشاہ کے تعلقات محدود ہوتے ہیں بہ نسبت خالق و مخلوق کے تعلقات کے.خالق و مخلوق کے تعلقات غیر محدود ہوتے ہیں.کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے عباد میں شامل ہوجاتا ہے.اس وقت دوسروں کی نسبت اس پر زیادہ فیض نازل ہونے لگتے ہیں اس وقت بسا اوقات وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا انسان ہو گیاہوں.
Page 461
اس وجہ سے اس تعلیم سے رو گردان ہو جاتا ہے.جس کے ذریعہ اسے یہ درجہ ملا تھا اور اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوجا تاہے اس لئے فرمایا کہ میں اِلٰہِ النَّاسِ کی پناہ چاہتاہوں کیونکہ ممکن ہے کہ قرآن پڑھ کر تم اتنے قریب پہنچ جائو کہ خدا کے عبد بن جائو اور عبداللہ کہلائو مگر ہوسکتا ہے کہ اس وقت تمہیں یہ خیال پیدا ہو کہ ہم بہت بڑے بن گئے ہیں.اس لئے دعا مانگو کہ الٰہی ہم تجھے معبودیت کاہی واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اس وقت بھی تجھ سے رو گردان نہ ہوجائیں.بلکہ ہمیشہ اپنے عبد ہی بنائے رکھنا.