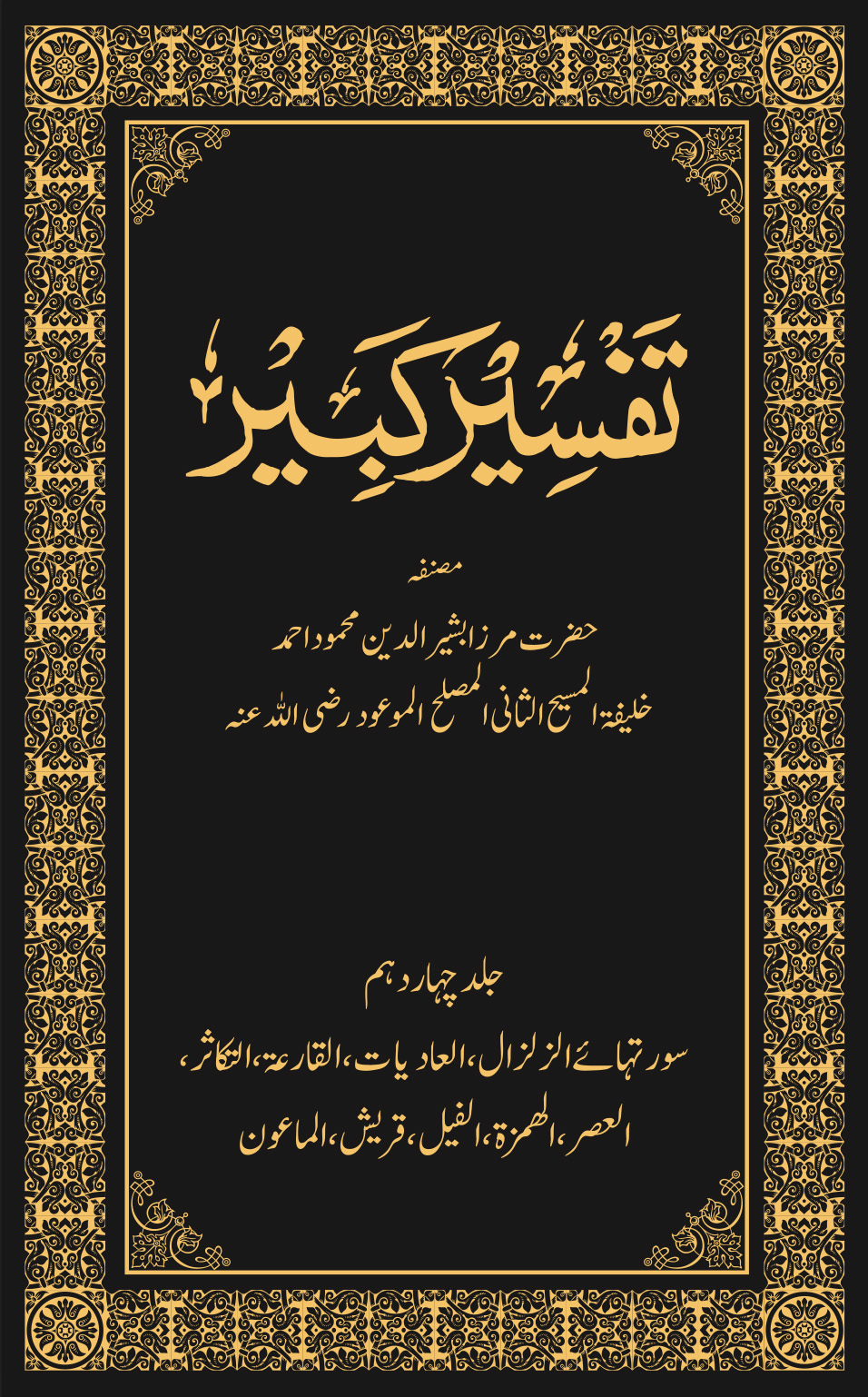Complete Text of Tafseer-e-Kabeer Volume 14
Content sourced fromAlislam.org
Page 5
سُوْرَۃُ الْزِلْزَالِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ زلزال.یہ سورۃ مکی ہے وَ ھِیَ ثَـمَانِیَ اٰیَاتٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَفِیْـھَا رُکُوعٌّ وَّ احِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے سوا آٹھ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے.سورۂ زلزال مکی ہے مجاہد، عطاء اور ابن عباسؓ کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے قتادہ اور مقاتل اسے مدنی کہتے ہیں (روح المعانی زیر سورۃ زلزال) چونکہ ایک صحابی کی تائید پہلے قول کو حاصل ہے اس لئے ترجیح اسی قول کو ہوگی کہ اسے مکی سمجھا جائے.مگر قرآن کریم کے مروّج نسخے جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کے اوپر مدنی ہی لکھا ہوا ہے.ویری نے اسے مکی قرار دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کی ابتدائی آیتیں مدنی سٹائل سے ملتی ہیں مگر ہے یہ مکی.(A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry v:4 p268) یہ امر ہمیشہ ہی میرے لئے حیرت کا موجب رہتا ہے کہ یوروپین مستشرق جو زبان دانی کے لحاظ سے عام مولویوں سے بھی عربی کا علم کم رکھتے ہیں وہ سورتوں کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ کرتے وقت ان کے سٹائل کوکیوں زیر بحث لے آتے ہیں جبکہ ان کی علمی قابلیت ہرگز ایسی نہیں کہ وہ عربی کو اچھی طرح سمجھ سکیں کجا یہ کہ عربی زبان کے سٹائل کو پہچاننے کی قابلیت ان میں موجود ہو.وہ جب بھی قرآن کریم کے متعلق اس کے سٹائل کے لحاظ سے کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ فلاسفہء یونان یا فلاسفہء جرمن کے متعلق اپنی رائے ظاہر کررہا ہو.اصل بات یہ ہے کہ وہ چونکہ روایت و تاریخ اسلام کے علم سے کورے ہوتے ہیں تاریخی شواہد اور علم الروایات کی شہادت سے چونکہ کوئی نئی روشنی نہیں ڈال سکتے اِدھر انہیں اپنی علمیت جتانا بھی مقصود ہوتا ہے وہ کسی اسلامی مقولہ کی تصدیق سٹائل کے نام سے کر دیتے ہیں اس طرح کسی علمی روایت کا بھی ساتھ رہا اور سٹائل کے نام سے اپنی علمی مہارت کا بھی ثبوت دے دیا.گو حقیقتاً قرآن کریم تو الگ رہا وہ عام عربی کتب کا سٹائل بیان کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتے.ترتیب سورۃ سورۂ زلزال کا سورۂ بینہ سے تعلق پچھلی سورۃ میں قرآن کریم کا وہ اثر بیان کیا گیا تھا جو ابتدائی زمانہ میں اس سے ظاہر ہونا تھا اب اس سورۃ میں اس کے آخری زمانہ کے اثر کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا ہے
Page 6
کسی اور سورۃ کا ایک ٹکڑا معلوم ہوتی ہے.(A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry v:4 p268) مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناواقف آدمی اپنی ناواقفیت کے نتیجہ میں ایک بات کہہ دیتا ہے اور وہ نکل سچی آتی ہے درحقیقت ویری کا یہ کہنا کہ یہ سورۃ اپنی ذات میں مکمل نظر نہیں آتی بلکہ کسی اور سورۃ کا ٹکڑا معلوم ہوتی ہے نادانستہ گونا مکمل اعتراف ہے اس امر کا کہ اس سورۃ کا مضمون پہلی سورۃ کا تتمہ ہے چونکہ ویری کو علمِ قرآن حاصل نہیں اس کا ذہن ادھر تو گیا کہ یہ سورۃ نا مکمل ہے لیکن اس کا ذہن ادھر نہ جا سکا کہ یہ کس دوسری سورۃ سے مل کر مکمل مضمون دیتی ہے.اس کی مثال ابن صیاد یہودی کی طرح ہے جس کا دعویٰ تھا کہ دل کی بات بوجھ لیتا ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۂ دخان کا مضمون دل میں رکھ کر اس سے پوچھا کہ بتا میرے دل میں کیا ہے تو دُخ دُخ کہہ کر رہ گیا(سنن ابو داؤد، کتاب الملاحـم باب خبر ابن صیاد).اسی طرح یہ پادری ویری اصل نکتہ معلوم نہ کر سکا کہ اس کا مضمون تتمہ ہے سورہ ٔبینہ کے مضمون کا.اس لئے غور سے دیکھنے والی لیکن نا تجربہ کار اور اسرار قرآنی سے نا واقف آنکھ کو یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سورۃ پہلی سورۃ کے مضمون سے شدید تعلق رکھتی ہے.ہاں وہ اتنا بھانپ گئی کہ یہ سورۃ کسی دوسری سورۃ کاٹکڑا نظر آتی ہے.سورۃ الزلزال کے متعلق بعض روایات اور مفسرین کا ان سے سورۃ الزلزال کی فضیلت ثابت کرنا اس سورۃ کی نسبت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے احمد ابودائود اور نسائی نے روایت کی ہے کہ اَتٰی رَجُلٌ رَسُوْلَ ﷲِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقْرِأْنِیْ یَا رَسُوْلَ اللہِ قَالَ اِقْرَأْ ثَلَاثًا مِّنْ ذَوَاتِ الٓرٰ فَقَالَ الرَّجُلُ کَبُـرَ سِنِّیْ وَ اشْتَدَّ قَلْبِیْ وَ غَلُظَ لِسَانِیْ قَالَ اِقْرَأْ ثَلَاثًا مِّنَ الْمُسَبِّحَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِہِ الْاُوْلٰی وَقَالَ وَلٰکِنْ اَقْرِأْنِیْ یَا رَسُوْلَ ﷲِ سُوْرَۃً جَامِعَۃً فَاَقْرَأَہٗ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَہَا حَتّٰی فَرِغَ مِنْـھَا قَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِیْ بَعَثَکَ بَالْـحَقِّ لَا اَزِیْدُ عَلَیْـھَا فَقَالَ رَسُوْلُ ﷲِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ یعنی ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن شریف پڑھائیں.آپ نے فرمایا الٓرٰ والی تین سورتیں پڑھا کرو.اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں بڈھا ہوگیا ہوں حافظہ خراب ہو گیا ہے زبان سخت ہو گئی ہے اس لئے مجھے کوئی اور سورۃ بتائیے.آپ نے فرمایا اچھا تین سَبَّحَ والی سورتیں
Page 7
پڑھا لیا کرو فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِہِ الْاُوْلٰی اس نے وہی بات جو پہلے کہی تھی پھر دہرائی کہ میں بوڑھا ہوگیا ہوں حافظہ خراب ہوگیا ہے اور زبان سخت ہوگئی ہے پھر اس نے کہا یارسول اللہ مجھے کوئی ایک سورۃ ایسی بتادیجئے جو جامع ہو.اس پر آپ نے اسے اِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَھَا والی سورۃ سنائی اور کہا کہ یہ پڑھو یہاں تک کہ جب آپ یہ سورۃ پڑھ چکے تو اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھوں گا.فَقَالَ رَسُوْلُ اللہُ صَلیَّ اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ.اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹا آدمی یعنی کمزور اور بڈھا کامیاب ہوگیا.کامیاب ہو گیا.اس حدیث سے شرّاح اور مفسرین اس سورۃ کی فضلیت نکالتے ہیں لیکن درحقیقت اس شخص کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی سورۃ مجھے بتا دیں جس کا میں ورد کیا کروں جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے.کیونکہ اس شخص نے الٓرٰ کی سورتوں اور مسبّحات کی سورتوں کو لمبا بتایا ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قرآن سنا ہوا تھا ورنہ اسے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ الٓرٰ والی سورتیں لمبی ہیں یا مسبّحات والی سورتیں اس کی طاقت سے بڑھ کر ہیں.میں تو سمجھتا ہوں کئی معمولی قرآن شریف پڑھنے والوں کے سامنے اگر مسبّحات کا ذکر کیاجائے تو ان میں سے کئی کہہ دیں گے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ مسبّحات سے آپ کی کیا مراد ہے.مگر اس شخص نے آپ کی بات سن کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری طاقت سے بڑھ کر ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ نہ صرف اس نے سارا قرآن سنا ہوا تھا بلکہ اس طرح سنا ہوا تھا کہ وہ سورتوں کو الگ الگ پہچانتا تھا.دوسرے آپ کا یہ فرمانا کہ تو تین فلاں سورتیں پڑھ.اس کے صاف معنے یہ ہیں کہ آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضرور آپ سے ہی پڑھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی سورۃ پڑھنے کے لئے بتادیں جیسے ہمارے ملک میں کئی لوگ آتے ہیںتو کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے.اسی طرح حدیث کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ حضور مجھے کوئی ایسی سورۃ بتا دیں جس کا میں وظیفہ کیا کروں.آپ نے اسے الٓرٰ والی تین سورتیں بتا دیں.اگر زلزال کی کوئی خاص فضیلت ہوتی تو آپ اسے پہلے الٓرٰ والی تین سورتیں کیوں بتاتے پھر تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے اسے سورۂ زلزال بتا دیتے.اس پر جب اس نے کہا کہ میں بڈھا ہوں حافظہ خراب ہے اور زبان بھی سخت ہوگئی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ بھی سورۂ زلزال نہیں بتائی بلکہ مسبّحات بتائیں.اگر اس حدیث سے سورۂ زلزال کی فضیلت کا استنباط کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ عجیب بات نظر نہیں آتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعلیٰ سورۃ تو نہ بتائی اورادنیٰ سورتیں بتا دیں.پس اس حدیث سے شرّاح
Page 9
اور آپ نے فرمایا اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ اَفْلَحَ الرُّوَیْـجِلُ اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا تو اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے فرمایا اسے واپس بلائو.جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا.اُمِرْتُ بِیَوْمِ الْاَضْـحٰی جَعَلَہُ اللہُ عِیْدًا لِھٰذِہِ الْاُمَّۃِ فَقَالَ لَہُ الرَّجُلُ أَرَأَیْتَ اِنْ لَّمْ اَجِدْ اِلَّا مَنِیْحَۃً اُنْثٰی اَفَاُضَـحِّیْ بِـھَا قَالَ لَا وَلٰکِنَّکَ تَاْخُذُ مِنْ شَعْرِکَ وَتُقَلِّمُ اَظْفَارَکَ وَتَقُصُّ شَارِبَکَ وَ تَـحْلِقُ عَانَتَکَ فَذٰلِکَ تَـمَامُ اُضْـحِیَّتِکَ عِنْدَ اللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ( سنن نسائی کتاب الضحایا باب من لم یجد الاضحیۃ).یہی حدیث ابو دائود اور نسائی نے بھی روایت کی ہے.مگر عبد اللہ بن عمرو سے نہیں بلکہ عبد الرحمٰن الحضرمی سے.گویا اصل حدیث کے آخر میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس بلا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یوم الاضحی یعنی عید الاضیحہ کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اس اُمت کے لئے عید بنائی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بتایئے یعنی آپ کی اس بارہ میں کیا رائے ہے کہ اگر میرے پاس اونٹ یا بکری نہ ہو صرف میرے پاس ایک اونٹنی ہو جو کسی نے تحفۃً دی ہو تو کیا میں اسے عید الاضحیہ پر ذبح کر دوں؟ رسو ل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نہ.ایسا ہرگز نہ کرنا بلکہ اپنے بال منڈوانا، اپنے ناخن ترشوانا، اپنی مونچھوں کے اگلے حصے کے بال چھوٹے کروانا اور زیر ناف بالوں پر اُسترا پھیرنا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری قربانی ہو گی.کسی سورۃ کے ثلث یا ربع قرآن ہونے کا مطلب ان روایات کے متعلق یہ نکتے یاد رکھنے کے قابل ہیں.اوّل یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک چھوٹی سی سورۃ کو نصف القرآن یا ثلث القرآن یا ربع القرآن کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو عالم، جاہل، بُڈھے، جو ان سب کے لئے ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم خود متواتر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں، یاد کریں اور اس پر عمل کریں اور یہ زور اس حد تک دیا گیا ہے کہ ایک سچا مسلمان اس سے شدید طور پر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا.جو شخص اسلام کے ساتھ کچھ بھی حقیقی دلچسپی رکھتا ہے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو وہ اس بات کا اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کی ایمانی زندگی کا مدار صرف اور صرف قرآن کریم پر ہے اور یہ کہ وہ اتنا ہی خدا تعالیٰ کے قریب جا سکتا ہے جتنا قریب کہ وہ قرآن کریم کے گیا ہے.ان حالات میں ایک بڈھا جس کی زبان نہیں چلتی ایک جاہل عورت جس کا حافظہ کام نہیں دیتا ایک غیر عرب جو عربی زبان سے مانوس نہیں ہے اور اس قدر فرصت بھی اس کو نہیں کہ وہ عمر کا معتد بہ حصہ لگا کر قرآن کریم کو حفظ کر سکے ایسے لوگوں کے دلوں کا اس تاکید کو سن کر کیا حال ہو سکتا تھا پس آپ نے ان الفاظ میں ان لوگوں کی دلجوئی کی ہے اوربتایا ہے کہ ثواب قابلیتِ عمل کے لحاظ
Page 11
نہیں ملتا تو قرآن عظیم میں اس مسئلہ کو تلاش کرتے ہیں.اس سے اُمت میں غورو فکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علم میں زیادتی ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے سورۂ فاتحہ کو سارے قرآن کریم کا قائم مقام نہ تو ہم مانتے ہیں اور نہ آج تک کسی نے ایسا کیا ہے.اور ان احادیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے فلاں سورۃ پڑھی اسے نصف یا ثلث یا ربع قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل گیا.مگر سورۂ فاتحہ کی نسبت تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ جس نے سورۂ فاتحہ پڑھی اسے سارے قرآن کا ثواب مل گیا مضمو ن کا ہونا اور شے ہے اور ثواب کا ملنا بالکل اور شے ہے.اگر یہاں بھی مضمون مراد ہے تو اس نصف یا ثلث یا ربع کی تعیین ہونی چاہیے تھی.جس نصف یا ثلث یا ربع کا یہ سورتیں خلاصہ ہیں آخر قرآن کریم کا نصف کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی کہ پہلا نصف مراد لے لیا جائے.اس صورت میں بھی کہ دوسرا نصف مراد لے لیاجائے اور اس صورت میں بھی کہ قرآن کریم کو متفرق جگہوں سے نکال کر اس کا نصف یا ثلث یا ربع مراد لے لیا جائے.سورۂ فاتحہ میں تو ایک تعیین کر دی گئی تھی کہ وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اس تعیین کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم سورۂ فاتحہ پڑھتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ اس میں سارے قرآن کریم کا مضمون کس طرح آگیا ہے یا جب ہم سورۂ بقرہ پڑھتے ہیں یا آلِ عمران پڑھتے ہیں یا نِسَآء پڑھتے ہیں یا مائدہ پڑھتے ہیں یا انعام پڑھتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں کہ اس میں سورۂ فاتحہ کے مضامین کس طرح بیان ہوئے ہیں مگر یہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ کون سا نصف ہے جس کے برابر سورۂ زلزال ہے یا کون سا ثلث ہے جس کے قائم مقام سورۂ اخلاص ہے یا کون سا ربع ہے جس کی قائم مقام سورۂ کافرون اور سورۂ اِذَاجَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ ہے پس ان سورتوں پر غور کر کے ہم کس دوسرے نصف یا ثلث یا ربع کے مضمون پر غور کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ان میں ان سورتوں کا مضمون زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے.پس محض یہ کہہ دینا کہ فلاں سورۃ نصف قرآن کے برابر ہے اور فلاں ثلث قرآن یا ربع قرآن کے برابر فائدہ کے لحاظ سے بالکل بے کار ہے.نہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان سورتوں میں کسی نصف یا کسی ثلث یا کسی ربع کا مضمون خلاصۃً بیان ہوا ہے نہ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کس نصف یا ثلث یا ربع میں ان سورتوں کے مضامین کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے.چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کا وہ نصف یا ثلث یا ربع معین کیا جاتا جس کے مضامین کو ان سورتوں میں بیان کیا گیا تھا تا کہ مومن اس نصف یا ثلث یا ربع کے مضامین کا ان سے مقابلہ کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے جیسے سورۂ فاتحہ پر غور کر کے ہم سارے قرآن کریم کے مضامین کو اخذ کرسکتے ہیں اور سارے قرآن کریم میں زیادہ تفصیل کے ساتھ وہی مضمون پاتے ہیں جو سورۂ فاتحہ میں بیان ہوا ہے مگر آپ نے اس نصف یا ثلث یا ربع کا کوئی ذکر نہیں کیا جس کے یہ برابر ہیں.پس صاف ظاہر ہے کہ اس جگہ
Page 12
اشارہ مضمون کی طرف نہیں.خود حدیث کے الفاظ بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں.چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مَــنْ قَــــرَأَ فِیْ لَـــیْـــلَـۃٍ اِذَا زُلْــزِلَـــتْ کَانَ لَــــہٗ عَــدْلُ نِــصْـــفِ الْقُراٰنِ.(فـتح البیان زیر سورۃ الزلزلۃ)آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مضمون نصف قرآن کے برابر ہے جیسے سورۂ فاتحہ کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ خلاصہ ہے سارے قرآن کا.بلکہ آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ کا ثواب نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے.مگر یہ معنے بھی ایسے ہیں جنہیں کوئی عقل مند درست تسلیم نہیں کرسکتا.کیونکہ اگر اس چھوٹی سی سورۃ کاثواب نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے.تو پھر کسی کو سارا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ اس میں نصف قرآن یا ربع قرآن کا مضمون بیان کیا گیا ہے تو پھر اس نصف یا ربع کی تعیین ہونی چاہیے تھی جن کا مضمون اس سورۃ میں خلاصۃً بیان کیا گیا ہے تا کہ جو شخص بھی اس سورۃ کو پڑھتا وہ سمجھتا کہ اس میں فلاں نصف یا فلاں ربع کے تمام مضامین آ گئے ہیں.پس اگر ہم ان احادیث کو صحیح تسلیم کر لیں تو پھر وہی بات بن جاتی ہے جو دعائے گنج العرش کے متعلق مشہور ہے کہ جس نے اسے ایک دفعہ پڑھ لیا اسے آدمؑ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی عبادت کا ثواب مل گیا اس کے بعد انسان کو اور کیا چاہیے.جب اتنی آسانی سے کسی کو سارے نبیوں اور بزرگوں اور ولیوں کی عبادت کا ثواب مل رہا ہو تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ محنت کرے اور اپنے نفس کو مشقتوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ دعائے گنج العرش پڑھ لے گا اور مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیاجو مجھ سے پہلے نبیوں اور ولیوں نے حاصل کیا تھا.پس اگر ثواب مراد ہے تو اس حدیث کا وہی مفہوم بن جاتا ہے جو دعائے گنج العرش کا ہے مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان احادیث کا یہ مطلب نہیں ہوسکتا.درحقیقت ان احادیث کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ ایک کمزور انسان جس کا حافظہ کمزور ہے اگر تین چار چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کر لے تو اسے ویسا ہی ثواب مل جائے گا جیسے ایک اچھے حافظہ اور علم رکھنے والے انسان کو جس نے سارا قرآن یاد کر لیا.جزائے اعمال کا اسلامی فلسفہ اس طرح ایک تو جزائے اعمال کا اسلامی فلسفہ بتا دیا گیا کہ اسلامی فلسفہ یہ نہیں کہ اگر کسی کے پاس زیادہ سامان ہوں گے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا بلکہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق قربانی کا حق ادا کر دیتا ہے تو وہ ثواب میں اس شخص سے یقیناً بڑھ جائے گا جس نے گو بظاہر اس سے زیادہ قربانی کی مگر اپنی طاقت سے کم حصہ لیا.مثلاً اگر کسی شخص کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے اور وہ اس میں سے دس ہزار روپیہ
Page 13
خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیتا ہے اور دوسرے شخص کے پاس صرف سو روپیہ تھا مگر اس نے سو کا سو روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ایک سوروپیہ خرچ کرنے والا دس ہزار روپیہ چندہ دینے والے سے زیادہ ثواب حاصل کرے گا کیونکہ اس نے اپنی ساری پونجی خدا تعالیٰ کی راہ میں لٹا دی لیکن دس لاکھ والے نے اپنی ساری پونجی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کی بلکہ اس کا سواں حصہ خرچ کیا.پس وہ دس ہزار روپیہ خرچ کرنے کے باوجود ثواب میں اس شخص سے بہت کم رہے گا جس نے سوروپیہ خرچ کیا ہے.اس کی ایک موٹی مثال موجود ہے حضرت ابوبکر ؓ مال میں حضرت عثمانؓسے بہت کم تھے.حضرت عثمانؓنے صرف ایک غزوہ کے موقع پر اتنا چندہ دے دیا تھا کہ شائد ابو بکرؓ کو سالوں میں بھی مجموعی طور پر اتنا چندہ دینے کا موقع نہیں ملاہو گا.مگر باوجود اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمات میں حضرت ابوبکرؓ کی تعریف حضرت عثمانؓ سے زیادہ کی ہے اس کی وجہ درحقیقت یہی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بعض دفعہ اپنا سارا مال ہی خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تھا لیکن حضرت عثمانؓ کے متعلق یہ بات ثابت نہیں.حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ اب کی دفعہ صدقہ و خیرات میں ابوبکرؓ سے بڑھ جائوں.ان کا اندازہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں جو چندہ دیا ہے وہ نصف مال سے کم ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا کہ میں اب کی دفعہ اپنا نصف مال دے دوں گا اور اس طرح ابوبکرؓ سے بڑھ جائوں گا.حضرت عمرؓ کہتے ہیں میں مال سے لداپھندا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا اور میں اپنے دل میں بڑا خوش تھا کہ آج ابوبکرؓ سے ضرور بڑھ جائوں گا.جب میں وہاں پہنچا تو ابوبکرؓ پہلے ہی کھڑے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ابوبکرؓ تم نے اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑا؟ اور ابوبکرؓ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ! اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے حضرت عمرؓ کہتے ہیں جب میں یہ بات سنی تو میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ اس شخص سے بڑھنا ناممکن ہے(ابو داؤد کتاب الزکاۃ باب فی الرخصۃ فی ذالک) اب دیکھو جہاں تک مال کا سوال ہے عثمانؓ زیادہ مال دار تھے، جہاں تک رقموں کا سوال ہے جو رقمیں حضرت عثمانؓنے دیں ابوبکرؓ نے نہیں دیں مگر باوجود اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکرؓ کی تعریف کرتے ہیں عثمانؓکی اتنی تعریف نہیں کرتے.اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے مال کی نسبت سے ابوبکرؓ نے جو قربانی کی وہ عثمانؓنے نہیں کی.پس یہاں جزائے اعمال کا اسلامی فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جزائے اعمال کے متعلق اسلامی مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کمیت کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ دینے والے کی قربانی کی طاقت کے مقابلہ میں کیا نسبت رکھتا ہے.اگر دی ہوئی چیز بہت چھوٹی سی ہے مگر
Page 14
تمام حالات کو مدّ نظر رکھتے ہوئے اس میں ساری طاقت اتنی ہی تھی تو وہ اس شخص سے بڑھ جائے گا جس نے اس سے زیادہ دیا.مگر وہ قربانی کی طاقت زیادہ رکھتا تھا.دوسرے کمزور اور نحیف اور نا توان آدمیوں کو حسرت اور دل شکنی سے بچا لیا گیا ہے جس کا حافظہ کمزور ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو مارا گیا نا معلوم قیامت کے دن اچھے حافظوں والے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی وجہ سے کیا کیا ثواب لے جائیں گے وہ جب اس حدیث پر آئے گا کہ جس نے سورۃ الزلزال پڑھی اسے نصف قرآن کا ثواب مل گیا اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگ جائے گا اور وہ کہے گا سورۃ الزلزال یاد کرنے کی تو مجھے تو فیق حاصل ہے آئو میں اسے یاد کر کے ثواب میں اس شخص کے برابر ہو جائوں جس نے نصف قرآن یادکیا ہوا ہے یا سورۂ اخلاص تو میں آسانی سے حفظ کر سکتا ہوں یا سورۂ کافرون یاد کرنا تو کوئی مشکل امر نہیں یا سورۂ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ تو میں اچھی طرح یاد کر سکتا ہوں اور اس طرح ان چار چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کر کے میںثواب میں اس شخص کے برابر ہو سکتا ہوں جس نے سارا قرآن حفظ کیا ہوا ہے.مایوسی اس کے دل سے دور ہو جائے گی اس کے حسرت و اندوہ کے جذبات مسرت و انبساط سے تبدیل ہو جائیں گے اور اس کا دل پکار اٹھے گا کہ میرے لیے گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی اپنے قرب و انعامات کا دروازہ کھولا ہوا ہے.اس کا مزید ثبوت کہ یہی معنے اس جگہ مراد ہیں یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے ایک جامع سورۃ بتائیے جس کا میں ورد کیا کروں اسے آپ نے پھر بلا کر کہا کہ عید الاضحیہ کا بھی اسلام میں حکم پایا جاتا ہے.اب بظاہر یہ بات آپ کی نعوذ باللہ کیسی بے جوڑ معلوم ہوتی ہے کہ آپ اسے واپس بلاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اسے اسلام کے اور ضروری احکام کی طرف توجہ دلائیں اسے کہتے ہیں کہ عید الاضحیہ منانا بھی اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے حالانکہ قرآن پڑھنے کے علاوہ اسلام میں نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، جہادکا بھی حکم ہے یہ عیدالاضحیہ منانا کون سا حکم ہے کہ آپ نے اسے خاص طور پر واپس بلایااور فرمایا کہ میاں ذرا یہ بھی سن جانا کہ اسلام میں عید الاضحیہ منانے کا بھی حکم ہے.اگر آپ اسے بتاتے تو یہ بتاتے کہ صرف قرآن ہی یاد نہیں کرنا بلکہ نماز بھی پڑھنا ہے بتاتے تو یہ بتاتے کہ زکوٰۃ کا بھی اسلام میں حکم دیا گیا ہے بتاتے تو یہ بتاتے کہ صرف سورۂ زلزال پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کرنا بلکہ روزے بھی رکھنا.بتاتے تو یہ بتاتے کہ تم نے جہاد بھی کرنا ہے یا اور بڑے بڑے اہم مسائل جن کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے ان کی طرف اس کی توجہ کو پھیرتے مگر آپ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر صرف اتنا فرماتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کا بھی حکم پایا جاتا ہے.یہ بات ایسی ہے کہ اگر
Page 15
اس پر پورے طور پر غور کر کے اس کا صحیح مفہوم نہ نکالا جائے تو ظاہر ی صورت میں یہ بات بالکل ویسی ہی بن جاتی ہے جیسے ایک لونڈی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ سحری کے وقت اٹھ کر بیٹھ جاتی اور سحری بھی کھاتی مگر روزہ نہیں رکھتی تھی.گھر کی مالکہ رحم دل اور نیک سیرت عورت تھی اس نے سمجھا کہ یہ ہماری خاطر اٹھتی ہے تا کہ کام میں کچھ مدد دے سکے ورنہ اس کا منشاء اگر روزہ رکھنا ہوتا تو روزہ بھی رکھتی چونکہ یہ روزہ نہیں رکھتی اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کے وقت یہ ہماری خاطر ہی تکلیف کر کے اٹھ بیٹھتی ہے ایک دن مالکہ نے اس سے کہا تو نے روزہ تو رکھنا نہیں ہوتا اس لئے سحری کے وقت نہ اٹھا کرہم کام خود کر لیا کریں گے وہ کہنے لگی بی بی نماز میں نہیں پڑھتی روزہ میں نہیں رکھتی سحری بھی نہ کھائوں تو کافر ہی ہو جائوں.جس طرح اس لونڈی نے نماز اور روزہ سے سحری مقدم کر لی تھی اسی طرح اس حدیث کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ ایک تورات کو سورۂ زلزال پڑھ لی اور ایک عید کے دن قربانی کا بکرا کھا لیا بس اسلام کے سارے احکام پر عمل ہو گیا مگر اس حدیث کے ہرگز یہ معنے نہیں ہیں آپ کا اسے واپس بلانا اور اسلام کے اور تمام احکام کو نظر انداز کر کے صرف اتنا فرمانا کہ عید الاضحیہ کا بھی اسلام میں حکم پایا جاتا ہے اور پھر اس کے یہ کہنے پر کہ مجھے ایک اونٹنی تحفہ میں ملی ہوئی ہے کیا میں اسے قربان کر دوں آپ کا یہ فرمانا کہ تجھے جانور قربان کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر تو بال منڈواتا ہے مونچھوں کے بال ترشواتا ہے ناخن کٹواتا ہے زیر ناف بالوں پر اُسترا پھیرتا ہے تو یہ بھی تیری قربانی ہے درحقیقت اس لیے تھا کہ آپ اپنی پہلی بات کی حقیقت اور فلسفہ اسے اور دوسرے سننے والوں کو بتانا چاہتے تھے چنانچہ جب اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو مجھے تحفہ کے طور پر ملی ہوئی ہے کیا میں اس اونٹنی کو ذبح کر دوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تمہارے جیسے غریب آدمی کے لیے بال منڈوانا اور ناخن ترشوانا ہی قربانی کا مترادف ہے اور اس طرح بتا دیا کہ جس طرح بال منڈوانا اور ناخن ترشوانا ایسے آدمی کے لیے قربانی کے برابر ہے جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو اسی طرح وہ شخص جس کا حافظہ کمزور ہے جس کی صحت خراب ہے یا جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور اس کی صحت حافظہ اور قویٰ زیادہ قرآن حفظ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے اس کا سورۂ زلزال کو یاد کر لینا ہی بڑی سورتوں یاقرآن کریم کو یاد کر لینے کے برابر ہے.یہ فلسفہ تھا جس کے بیان کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڈھے کو واپس بلائو تا کہ وہ بھی اس فلسفہ سے آگاہ ہو جائے اور صحابہؓ بھی سمجھ لیں کہ میرا اس سے کیا منشاء ہے اگر معانی کی طرف اشارہ ہوتا تو طاقت والے کے لیے اور نہ طاقت والے کے لیے معانی کے لحاظ سے وہ سورۃ یکساں ہونی چاہیے تھی مگر آپ دونوں کے لیے ان سورتوں کا حفظ یکساں قرار نہیں دیتے بلکہ ایک مثال کے ذریعہ اس فرق کوواضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس
Page 16
طرح ایک غریب شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں صرف بال منڈوا کر اور ناخن ترشوا کر قربانی کے ثواب میں شریک ہو سکتا ہے اسی طرح وہ شخص جس کا حافظہ اور صحت زیادہ قرآن حفظ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس کا سورئہ زلزال کو یاد کر لینا ہی نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے پس بے شک سورۃ الزلزال یا سورۃ الاخلاص یا سورۃ الکافرون یا سورۃ النصر کے یاد کر لینے سے انسان کو نصف القرآن یا ثلث القرآن یا ربع القرآن کا ثواب مل جاتا ہے مگر ہر ایک کو نہیں.اس کمزور انسان کو جس کو صرف سورۃ الزلزال ہی یاد ہو سکتی تھی یا سورۃ الاخلاص ہی یاد ہو سکتی تھی یا سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر ہی یاد ہو سکتی تھیں وہ اگر سورۃ الزلزال پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسے اس نے نصف قرآن پڑھ لیا.پس یہاں معانی کا سوال نہیں نہ ہرشخص کا سوا ل ہے بلکہ صرف معذور کے لیے ثواب حاصل کرنے کا ایک رستہ کھولا گیا ہے.غرض اس شخص کو خاص طور پر بلا کر وہ حکم بتانا جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد سے بہت کم ہے صاف بتاتا ہے کہ آپ کا منشاء یہ تھا کہ یہ حکمت اس پر اور دوسروں پر واضح ہو جائے اور وہ اس دھوکے میںنہ پڑ جائیں کہ زلزال یا کوئی اور سورۃ درحقیقت نصف یا ثلث یا ربع قرآن کے برابر ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں.قرآن مجید کی سورتوں کے دولت قرار دینے میں حکمت (۲)دوسرا نقطہ قابلِ توجہ ان احادیث میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند سورتوں کے یاد ہونے کو ایک دولت قرار دیا ہے اس سے ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اپنی رسالت پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کلام کو جو آپ پر نازل ہوتاتھا کس قدر قیمتی سمجھتے تھے کہ جسے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی یاد ہو اس کی نسبت خیال فرماتے تھے کہ وہ اپنی ہرضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور محتاجوں اور ناداروں میں شامل کئے جانے کے قابل نہیں.یہ ایمان محض آپ کی راست بازی کا ہی ثبوت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ اس کلام نے آپ کے جسم کے ذرہ ذرہ پر قابو پا لیا تھا اور آپ اس کی اہمیت کو ہر دوسری شے پر مقدم سمجھتے تھے.(ب) اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہؓ کے ایمان پر بھی بڑا بھروسہ تھا اور آپ یقین رکھتے تھے کہ آپ کے صحابہ بھی قرآن کریم کو ایک عظیم الشان دولت سمجھتے ہیں.اگر آپ کے صحابہؓ اس خیال کے نہ ہوتے تو آپ کا اس صحابی کو یہ کہنا کہ جب تجھے چند سورتیں یاد ہیں تو تُو نکا ح کربے معنے ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی لڑکی ہی نہ دے گا تو وہ نکاح کیونکر کرے گا.اگر لڑکیاں اور لڑکیوں کے ماں باپ بھی قرآن کریم کو
Page 17
ایک عظیم الشان دولت نہ سمجھتے اور انہیں یہ یقین نہ ہوتا کہ قرآن کریم کا ایک جزو بھی انسان کو دولت مند بنا دیتا ہے تو آپ یہ حکم کبھی نہ دے سکتے تھے اور وہ شخص اس پر عمل بھی کبھی نہ کر سکتا تھا.(ج)اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے مسلمانوں کے لیے قرآن پڑھنا قرآن سمجھنے کے مترادف تھا اور قرآن سمجھنا اس پر عمل کرنے کے مترادف تھا ورنہ قرآن کی چند سورتوں کا یاد ہونا ان کے لیے دولت کس طرح کہلا سکتا تھا.آج کل مسلمان اوّل تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ایک بہت ہی چھوٹی تعداد قرآن پڑھنا جانتی ہے مگر اس چھوٹی تعداد میں سے اور بھی تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور ان بہت ہی تھوڑے لوگوں میں سے بالکل قلیل گروہ انگلیوں پر گنے جانے کے قابل ایسا ہے جو اس کو سمجھ کر باطن کو جانے دو اس کے ظاہر پر عمل کرتا ہے ان حالات میں ایسے لوگوں کا ادب کون کر سکتا ہے اور ایسی قوم جس کا اپنی مذہبی اور الہامی کتاب کی نسبت یہ رویہ ہے وہ کسی عزت کی مستحق ہی کس طرح ہو سکتی ہے.بِسْمِ اﷲِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور )بار بار رحم کرنے والا ہے( شروع کرتا ہوں) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَاۙ۰۰۲ جب زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا.حلّ لُغات.زُلْزِلَتْ.زُلْزِلَتْ: زَلْزَلَ سے مونث مجہول کا صیغہ ہے اور زَلْزَلَ اللہُ الْاَرْضَ زَلْزَلَۃً وَزِلْزَالًا وَزَلْزَالًا و زُلْزَالًا کے معنے ہیں اَرْجَفَھَا.اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہلا دیا اور زَلْزَلَ فُلَانًا کے معنے ہیں خَوَّفَہٗ وَحَذَّرَہٗ اسے خوف دلایا اور ڈرایا.اور زَلْزَلَ الْاِبِلَ کے معنے ہیں سَاقَھَا بِعُنْفٍ اونٹوں کو مار کوٹ کر چلایا اور اَلزَّلاَزِلُ کے معنے اَلشَّدَائِدُ وَالْاَھْوَالُ کے ہیں یعنی سختیاں اور خوف (اقرب) اِذَا جیسا کہ پہلے بھی بتایا جاچکا ہے مستقبل کے معنے رکھتا ہے اور اِذْ کا استعمال بالعموم ماضی پر ہوتا ہے.تفسیر.اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ میں زِلْزَالًا مصدر استعمال کرنے کی بجائے زِلْزَالَھَا کہنے کی وجہ عام قاعدہ کے رُو سے یہ آیت یوں ہونی چاہیے تھی اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالًا لیکن یہاں زِلْزَالًا کی بجائے زِلْزَالَھَا کہا گیا ہے.ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالًا کے تو صرف اتنے معنے
Page 18
ہوتے کہ زمین خوب ہلائی جائے گی.لیکن زِلْزَال کو اَرْض کی طرف اضافت دے کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس جگہ خاص مقدر زلزلہ مراد ہے نہ کہ عام زلزلہ خواہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو.عام زلازل تو آتے ہی رہتے ہیں خواہ سینکڑوں سال کے بعد آئیں.مگر بوجہ اس کے کہ وہ متواتر اور بار بار آتے ہیں وہ زِلْزَالَھَا کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے.زِلْزَالَھَا وہی زلزلہ کہا جا سکتا ہے جو زمین کے ساتھ تعلق رکھنے والا خاص زلزلہ کہلاسکتا ہو اور پھر ہو بھی ساری زمین پر تا کہ اس کے آنے پر صرف یہ نہ کہا جائے کہ زمین پر ایک زلزلہ آ گیا بلکہ یوں کہا جائے کہ زمین کا مخصوص زلزلہ یا مقدر زلزلہ آ گیا عبارت کی اس بناوٹ ہی کی وجہ سے مفسرین کا ذہن ادھر گیا ہے کہ یہاں زلزلۂ قیامت مراد ہے جب کہ ان کے نزدیک ساری زمین پر زلزلہ آئے گا اور زمین تہ وبالا ہو جائے گی.(فتح القدیر سورۃ الزلزال زیر آیت اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ) اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ میں بیان شدہ پیشگوئی کے پورے ہونے کا زمانہ زمین کی ایک دن تباہی تو قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے لیکن یہ کہ وہ زلزلہ کے ذریعہ سے ہو گی میرے علم میں کسی نص سے ثابت نہیں بلکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج قریب آ جائے گا اور سب دنیا اس کی گرمی کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی.(المعجم الکبیر للطبرانی باب المیم، المقدام بن معدی کرب الکندی) لیکن بہر حال اس آیت کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان سے یا تو قیامت مراد لی جا سکتی ہے یا پھر کوئی ایسا امر جو قیامت کے مشابہ ہو اور سب دنیا سے تعلق رکھتا ہو.میری ذاتی رائے یہی ہے جیسا کہ میں اگلی آیات سے اپنے استدلال کو پیش کروں گا کہ اس جگہ قیامت کُبریٰ مراد نہیں بلکہ اس کے قریب زمانہ میں ظاہر ہونے والا وہ عظیم الشان تغیر مراد ہے جو زمانہء مسیح موعود میں مقدر تھا اور جسے اس کے پھیلائو، اس کی اہمیت اور اس کے خطرناک نتائج کے لحاظ سے قیامت کہا جا سکتا ہے.زِلْزَال کے چار معنے زِلْزَال کے معنے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ہلانے، خوف زدہ کرنے اور ہوشیار اور چوکس کرنے کے ہیں.ان معنوں کے رُو سے اس آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ جب سب کی سب زمین کو ہلا دیا جائے گا، خوف زدہ کیا جائے گا اور ہوشیار کیا جائے گا ان معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ لازماً نکلتا ہے کہ اس جگہ زمین کا لفظ صرف زمین کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ اہل زمین بھی اس جگہ پر مراد ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں قریہ سے اہل قریہ اور عیر سے اہل عیر مراد لئے گئے ہیں سورئہ یوسف رکوع ۱۰ میں اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی زبان سے فرماتا ہے.وَ سْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَ الْعِيْرَ الَّتِيْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا اسی گائوں سے پوچھ لیجئے جس گائوں میں ہم تھے اور اسی گدھوں کے قافلہ سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم اس طرف آئے ہیں.اس جگہ
Page 19
گاؤں سے مراد گاؤں والے اور گدھوں کے قافلہ سے مراد گدھے کے سواروں یا ان کے چلانے والوں سے ہے اُردو میں بھی کہتے ہیں کہ سب گائوں کو اس کا علم ہے گائوں سے مراد اس جگہ گائوں والے لوگ ہوتے ہیں.اس جگہ بھی زمین اور اہل زمین دونوں آیت کے مفہوم میں شامل ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سب زمین ہلائی جائے گی اور اہلِ زمین بھی ہلائے جائیں گے،خوف زدہ کئے جائیں گے اور ہو شیار کئے جائیں گے.جہاں تک اس وقت تک کی تاریخ سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقشہ موجودہ زمانہ کا ہی کھینچا گیا ہے.چنانچہ جس حد تک زمین کے ہلانے کا سوال ہے یہی زمانہ ہے کہ جس میں ریلوں اور کارخانوں کی کثرت کی وجہ سے زمین کانپتی رہتی ہے اور جہاں تک اہل زمین کا سوال ہے مقابلہ کا ایسا بازار گرم ہے کہ متمدن دنیا میں چلتا ہوا انسان نظر آنا مشکل ہے.سب دوڑ رہے ہیں رات کو دنیا کی حالت کچھ ہوتی ہے تو صبح کو کچھ اور ہو جاتی ہے.زمین رات اور دن چلنے والی ریلوں کی وجہ سے لرزہ بر اندام رہتی ہے اور دنیا کا کوئی گوشہ نہیں جہاں ریلوں اور کارخانوں نے زمین کو جنبش نہیں دے رکھی.کبھی کارخانوں کے علاقوں میں جائو یا ریل کی پٹڑی کے پاس ریل کے گذرتے وقت گذرو تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آیا ہوا ہے.زمین کے ہلائے جانے سے مراد اہل زمین کا ہلایا جانا پھر لڑائی کے سامان ایسے ایجاد ہوئے ہیں کہ ان سے زمین ہل رہی ہے.جنگیں ایسی خطرناک صورت اختیار کر گئیں ہیں کہ شہروں کے شہر اُڑا دیئے جاتے ہیں اور زمین میں غار پڑ جاتے ہیں.پھر زلازل بھی الٰہی کلام کے ماتحت بکثرت آ رہے ہیں اور علاقوں کے علاقے ان سے صاف ہو گئے ہیں پس جہاں تک زمین کے ہلنے کا سوال ہے ان ایام میں زمین ایسی ہلی ہے کہ دنیا میںاس کی نظیر پہلے نہیں ملتی کیونکہ پہلے صرف زلزلوں سے جو ممکن ہے بعض موجودہ زلزلوں سے بھی بڑے ہوں زمین ہلا کرتی تھی مگر اب (۱)زلزلوںسے اور متواتر زلزلوں سے اور عالمگیر زلزلوں سے ہل رہی ہے (۲) تو پوں، ہوائی جہازوں کے بموں، ڈائنامیٹ اور اب ایٹم بموں کے ذریعہ سے جو ساری دنیا اور ہر خطہ زمین پر اثر انداز ہوئے ہیں زمین ہلی ہے اور بہت بُری طرح ہلی ہے اور یہ اشیاء پہلے زمانہ میں موجود ہی نہیں تھیں اسی زمانہ میں ایجاد ہوئی ہیں (۳) ریلوں، زمین دوز ریلوں اور کارخانوں کی وجہ سے جو قطب شمالی سے قطب جنوبی تک اور مغرب سے مشرق تک پھیلے ہوئے ہیں زمین روزو شب ہل رہی ہے اور اگر یہی ترقی جاری رہی تو ہلتی چلی جائے گی.دوسرے معنے اہل زمین کے ہیں.اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس طرح ہلائے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہلائے گئے انسانوں کے ہلنے کے یہ معنے ہوا کرتے ہیں اوّل لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے.دوم لوگوں میں خوف
Page 20
پیدا کیا جائے.سوم لوگوں میں غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو جو علاوہ اور اقسام کے مندرجہ ذیل امور سے ہوا کرتی ہے (الف) سیاسیات میں تبدیلی کی وجہ سے (با) معاشیات میں تبدیلی کی وجہ سے (ج)مذہبیات میں تبدیلی کی وجہ سے (د) اخلاقیات میں تبدیلی کی وجہ سے (ہ)علوم میں تبدیلی کی وجہ سے(و)اقتصادیات میں تبدیلی کی وجہ سے.یہ سارے کے سارے امور اہلِ دنیا کو ہلانے کے اس زمانہ میں ظاہر ہو رہے ہیں.ساکنین ارض میں بیداری اور تغیر اوّل: بیداری کا پیدا ہونا.پہلے زمانہ میں اگر بیداری پیدا ہوتی تھی تو صرف چوٹی کے چند آدمیوں میں پیدا ہوتی تھی کیونکہ اس سے پہلے دنیا کا نظام بادشاہت یا حکومتِ امراء پر چلا کرتا تھا اگر شاہی خاندان میں کوئی تبدیلی آتی یا حکومتِ امراء میں کوئی تغیر ہوتا تو وہ چند خاندانوں یا افراد تک محدود رہتا تھا عوام الناس کو نہ اس سے کوئی تعلق ہوتا تھا نہ دلچسپی سوائے اس کے کہ عوام الناس میں سے کچھ افراد نوکری کی وجہ سے اس لپیٹ میں آ جاتے تھے مگر اب جہاں دیکھو حکومتِ عوام ہے.اوّل تو بادشاہتیں مٹ گئی ہیں اگر قائم ہیں تو صرف نام کی.درحقیقت عوام کی بے پناہ طاقت ان کے پردہ میں اپنا کام کر رہی ہے جیسے انگلستان میں ہے، بیلجیم میں ہے، ہالینڈ میں ہے.آج یہ بیداری عوام الناس میں ایسے طور پر پیدا ہو رہی ہے اور یہ حِس کہ بادشاہت عوام کی ہے نہ کہ کسی شخص یا اشخاص کی ایسا غلبہ پکڑ چکی ہے کہ بادشاہت کا تخت اب قلعہ میں محدود نہیں رہا ہر شہر، ہر قصبہ، ہرگائوں، ہرگلی اور ہر گھر میں خواہ وہ دنیوی وجاہت کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا ہو یا کتنا ہی چھوٹا ہو آج ایک تختِ شاہی رکھا ہوا نظر آتا ہے ہر فرد اپنے دل میں بادشاہت کا برابر کا شریک اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے اس لیے جو تغیر بھی پیدا ہوتا ہے وہ صرف شاہی سینوں اور امراء کے سینوں میں حرکت پیدا نہیں کرتا بلکہ ملک کے ہر فرد کے قلب کی گہرائیوں میں ایک حرکت پیدا کر دیتا ہے، وہ حرکت جو پہلے زمانہ میں سمندر کی سطح پر پیدا ہوتی معلوم ہوتی تھی اب سمندر کو اس کی تہ تک ہلا دیتی ہے.اس حد تک کہ اس کے اندر رہنے والی مچھلیوں کے لئے زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تعلیم عام ہو چکی ہے، صنعت و حرفت عام ہو رہی ہے، جو علوم اور جو فنون پہلے خاص خاص لوگوں میں بطور ورثہ چلتے تھے اب دنیا میں اَلَمْ نَشْرَحْ ہو چکے ہیں.جو کام پہلے جادوگریاں سمجھے جاتے تھے اب گلی گلی میں ان کے جاننے والے پائے جاتے ہیں بڑھنے اور ترقی کرنے کی اُمنگ ہر کس و ناکس میں پیدا ہے اور پیدا کی جارہی ہے.دوسرے :تَـخْوِیْف بھی اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے سیاسی اور مذہبی اختلافات کو اس طرح بڑھایا جارہا ہے کہ ہرسمجھ دار انسان کا دل آج دھڑک رہا ہے کہ کل کو کیا ہو جائے گا.فرد فرد سے اور جتھہ جتھے سے اور قوم قوم سے اور ملک ملک سے خائف ہے اور ان کے خوف کو روز بروز ان کے لیڈر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ مقابلہ کی رو ح
Page 21
اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انصاف اور عدل کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں رہا.اس وجہ سے کوئی قوم دوسری قوم سے مطمئن نہیں، کوئی حکومت دوسری حکومت سے مطمئن نہیں اور چونکہ اب حکومت عوام الناس کے ہاتھ میں ہے جنگ کرنا یا صلح کرنا انہی کے قبضہ میں ہے اس لیے اپنی موجودہ حالت کو قائم رکھنے یا اس کو اور بڑھانے کی خاطر لیڈر اور حکومتیں عوام الناس کے جذبات کو اشتعال پر اشتعال دلاتی چلی جاتی ہیں تا ان کے اندر سکون پیدا ہو جانے کی وجہ سے دوسری قوم یا دوسری حکومت ان پر غالب نہ آجائے اس وجہ سے ایک نہ ختم ہونے والی حرکت قوموں میں پیدا ہو رہی ہے.تیسرے: تغیر اور تبدیلی بھی حرکت کا موجب ہوتی ہے یہ بھی اس حد تک پیدا ہو چکے ہیں کہ اب کوئی چیز پرانی کہلانے کی مستحق نہیں (الف) سیاسیات کو لے لو سیاست اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی.سیاست کے اصول ہی بالکل بدل چکے ہیں.پہلے سیاست نام تھا صرف ایک بادشاہ کے دوسرے بادشاہ سے تبادلۂ خیال کا.مگر اب تو حکومت عوام الناس کے ہاتھ میں ہے اب سیاست کا دائرہ صرف ملک کی حدود کے تصفیہ تک باقی نہیں رہ گیا بلکہ اب سیاست نام ہو گیا ہے انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں دخل اندازی کا پہلے زمانہ میں بادشاہوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا کہ غیر ملکوں کے لوگ کس طرح روزی کماتے، کھاتے یا کس طرح پڑھتے اور کیا سیکھتے ہیں یا کس قسم کی ان کی معیشت ہے یا ان کے ملکی قانون کیا ہیں اور کیا نہیں لیکن اب سیاست ان چیزوں میں دخل دیتی ہے اور ان چیزوں میں دخل دینا ضروری قرار دیتی ہے ایک طرف تو حریت و آزادی کے ڈھول بجائے جاتے ہیں دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہم غیرملکوں میں ایسی ہی حکومت قائم ہونے دیں گے جو حکومت ہمارے اصولِ سیاست کے مطابق ہو.کبھی کمزور حکومتوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ زبردست حکومتوںکو اپنے ملک کی کانیں سپرد کر دیں.کبھی اس بات پر مجبور کیا جاتاہے کہ ان کا بنکنگ سسٹم اس زبردست ملک کے مطابق ہو اور وہ وزیر مالیات اس دوسری حکومت سے مانگ کر لیں.کبھی مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کے کالج کھولنے کی ان کو اجازت دی جائے.کبھی خاص خاص پابندیاں تجارت پر اور صنعت اور حرفت پر لگا دی جاتی ہیں کہ کیا کیا چیز وہ بنائیں یا کیا کیا چیز وہ نہ بنائیں.غرض پرانی سیاست تو نئی سیاست کے مقابل پر ایک نادان بچہ معلوم ہوتی ہے.عوام کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور پرانا نظام اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے.معاشیات میں تبدیلی (با)معاشیات میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا.جو اشیاء پہلے زمانہ میں تعیّش اور امراء کا واحد حق سمجھی جاتی تھیں اب عوام کی ملکیت ہو رہی ہیں.جو کھانے آج متمدن ممالک کے غرباء کو مل رہے ہیں وہ پرانے زمانہ کے امراء کو بھی میسر نہ تھے.متمدن ممالک کا ایک غریب آدمی بھی ہزاروں میل
Page 22
پر بیٹھے ہوئے پیسفک کی سامن، پرتگال کی سارڈنیز، کیلے فورنیا کے آڑو اور ناشپاتیاں، اٹلی اور افغانستان کے انگور، آسٹریا اور جاپان کے مالٹے اور سنگترے، افریقہ کے کیلے اور ہندوستان کے آم اس بے تکلفی سے کھاتاہے کہ پرانے زمانہ کے امیر کو بھی یہ بات نصیب نہ تھی اور کھاتے ہوئے اپنی غربت کی شکایت بھی ساتھ ساتھ کرتاجاتا ہے.پرانے زمانہ کا آدمی مثلاً فراعنہء مصر کے وقت کا کوئی آدمی اگر زندہ ہو کر آجائے اور یورپ کے مزدور کو اپنا کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو شاید وہ یہ خیال کرے گا کہ فراعنہء مصر اب پہلے سے بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں اور شاید آرام و آسائش کے سامان انہیں اب پہلے سے بہت زیادہ میسر آنے لگ گئے ہیں.جس قدر لباس پرانے زمانہ میں درمیانی طبقہ کے لوگوں اور معمولی امیروں کو میسر نہ تھا آج کل متمدن ممالک کے غرباء کو اس سے بڑھ کر میسر ہے.جو تماشے بڑے بڑے بادشاہ دیکھتے تھے اور لوگ ان کی عیاشی پر انگشت بدنداں ہوتے تھے آج ایک غریب مزدور چار آنے کے پیسے دے کر انہیں دیکھتا ہے اور اس سابق بادشاہ کی طرح کبھی کبھی نہیں دیکھتا بلکہ روزانہ دیکھتا ہے.اِندرسبھااگر کوئی تھی تو آج کے سینمائوں کے سامنے وہ بالکل مات نظر آتی ہے.پرانے زمانہ کے ہندوستانی مہاراجگان کے سامنے یا اگر اِندر بھی کوئی مہاراجہ گذرا ہے تو اس کے سامنے جس لباس میں ملکائیں اور شہزادیاں آتی تھیں اگر اس ادنیٰ لباس میں آج سینمائوں میں کوئی ایکٹرس آ جائے تو شاید حاضرین پرانی جوتیاں مار مار کے اس کی سکرین کو پھاڑ ڈالیں.بیوی میاں کے تعلقات، والدین اور اولاد کے تعلقات، استاد اور شاگرد کے تعلقات آج کل پرانے تعلقات سے ایسے مختلف ہیں کہ پرانے زمانہ کا آدمی آج کل پیدا ہو تو شاید پاگل ہی ہو جائے.کسی وقت بیوی میاں کی خدمت کرتی تھی آج میاں بیوی کا کوٹ اور چھتری اٹھائے اٹھائے اس کے پیچھے پھرتا نظر آتا ہے کبھی میاں اور بیوی اپنے پیار کی باتوں کو اپنے عزیز ترین وجودوں سے الگ ہو کر بند کمروں میں ادا کیا کرتے تھے آج برسرِ عام میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈارلنگ ڈارلنگ کہتے ہوئے نہیں تھکتے.سٹیشنوں پر ہزاروں آدمیوں کے ہجوم میں مرد عورت کو اس طرح بوسہ دیتا نظر آتا ہے جس طرح پرانے زمانہ میں جسم پر سے خاک جھاڑ لیا کرتے تھے.والدین کو اولاد پر آج کوئی حق حاصل نہیں نہ اولاد والدین کا حق تسلیم کرتی ہے.والدین کی خدمت ایک فرسودہ خیال سمجھا جاتا ہے استاد پہلے آقا ہوتا تھا اب نوکر ہے.پہلے علم پڑھانے کو خواہ روپیہ کے بدلہ میں ہو احسان سمجھا جاتا تھا اب اسے اور خدمتوں کی طرح ایک خدمت قرار دیا جاتا ہے.امام مالک صاحب کی خدمت میں خلیفۂ وقت جس کی بادشاہت یورپ سے لے کر ایشیا کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی درخواست کرتا ہے کہ کچھ وقت
Page 23
میرے لڑکوں کی پڑھائی کے لیے بھی دیں اور وہ یہ منظور کر لیتے ہیں کہ وہ لڑکے بھی ان کے گھر پر حاضر ہو کر سبق لے لیا کریں.ایک دن بادشاہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے لڑکے کس قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں خود امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے امام مالک ؒ اٹھتے ہیں تو مامون دوڑ کر ان کے آگے ان کی جوتی رکھ دیتا ہے.بادشاہ کو پیارا امین تھا کیونکہ اس کی ماں اسے بہت پیاری تھی مگر یہ نظارہ دیکھتے ہی ہارون الرشید نے کہا تخت کا وارث غالباً مامون ہی ہو گا.مگر آج کے حالات گذشتہ زمانہ کے بالکل الٹ نظر آتے ہیں.مذہب کے خلاف رو (ج) مذہبیات.مذہب ایسا اوندھے منہ گرا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے.پہلے زمانہ کے لوگ مذہب میں کمزوری دکھاتے تھے تو دل میں نادم ہوتے تھے اور اپنے اعمال کو لوگوں سے چھپاتے تھے اب جو مذہب کا ادب کرے احمق سمجھا جاتا ہے.پہلے مذہب کے خلاف بولنا ایک جرمِ عظیم خیال کیا جاتا تھا اب مذہب کے حق میں بولنا اپنے احمق ہونے کا اعلان کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے.پہلے مذہب انسانوں پر حکومت کیا کرتا تھا اب انسان مذہب پر حکومت کرتا ہے.ہر حکومت اپنے اغراض کے مطابق ایک مذہب کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے.سو ویٹ رشیا کا گرجا سوویٹ اصول کو عین مسیحی تعلیم قرار دیتا ہے، امریکہ کا گرجا مسیحیت کو کمیونزم کے اصول کے خلاف بتاتا ہے.انگلستان کا گرجا ایک محدود بادشاہی ایک آئینی بادشاہی کو مسیحیت کا صحیح نقشہ بتاتا ہے.فرانس کا پادری ری پبلک کو انجیل کی حقیقی تصویر ثابت کرتا ہے فاسسٹ پادری فاسزم کو مذہب کی رُوح بتاتا ہے.ہندوستان میں کانگرس کے زور کے علاقوں میں سارا قرآن باغیانہ تعلیم سے پُر نظر آتا ہے اور انگریزی اثر کے نیچے اس کی تمام تعلیم مغربی ترقی کی تائید کرتی ہوئی ملتی ہے.جاپان میں شنٹوازم شہنشاہیت کی برکات کو پھیلانے والی معلوم ہوتی ہے.پہلے زمانہ میں کہا جاتا تھا جب مذہب کی آواز میں بھی کوئی اثر تھا، جب مذہب بھی انسانی زندگی کا کوئی جزو سمجھا جاتا تھاکہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اب موجود ہ فلسفہ ببانگِ بلند کمال دلیری سے علی الاعلان کہتا ہے ہم اس خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے.دنیا کو ایسے خدا کی ضرورت ہے جسے دنیا نے پیدا کیا ہے.صفائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ تمام خرابی اور تمام بربادی اور تمام تباہی جو دنیا پر آئی ہے وہ خدا تعالیٰ کے اس خیال کی وجہ سے آئی ہے جس کو دنیا کا خالق قرار دیا جاتا ہے دنیا کا آئندہ امن اور دنیا کی آئندہ بہبودی اور دنیا کی آئندہ ترقی اسی امر پر منحصر ہے کہ جس طرح عوام الناس اپنے لیے بادشاہت مقرر کرتے ہیں مگر اس کے اختیارات وہ خود تجویز کرتے ہیں اسی طرح کہا جاتا ہے وہی مذہب دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے جو ایسا خدا پیش کرے جس کے خیالات اور جس کے اعمال عوام الناس آپ مقرر کریں.اس کے علاوہ علمی ترجمانی مذاہب کی ایسی ہوئی ہے
Page 24
کہ الامان والحفیظ.آج کی مسیحیت سو سال پہلے کی مسیحیت نہیں ہے نہ ہندو ازم آج سے سو سال پہلے کی ہندو ازم ہے اور نہ اسلام آج سے سو سال پہلے کا اسلام ہے.پرانے اصول کو بوسیدہ اور فرسودہ خیالات بتایا جاتا ہے.نصوص صریحہ قطعیہ کی تاویل کی جاتی ہے.عبادات کو غیر ضروری اور عقائد کو اوہام قرار دیا جاتا ہے اور یہ دہریوں کی طرف سے نہیں ہو رہا خود مذاہب کے پیرو کاروں کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو مردُود اور لا مذہب قرار دیا جاتا ہے.غرض وہی حال ہے جو حسرتؔ نے کہا ہےکہ ؎ خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسنِ کرشمہ ساز کرے (د) چوتھا اہم مسئلہ اخلاقیات کا ہے اس میں بھی ایک زلزلہ آ گیاہے.اخلاق میں سے بڑے بڑے مسائل صداقت، امانت، عفت اور انصاف ہیں ان امور کے متعلق بھی اس زمانہ کا نظریہ بالکل بدل گیا ہے.اخلاق میں تنزّل صداقت کا جو مفہوم پہلے سمجھا جاتا تھا اب نہیں ڈپلومیسی یعنی سیاست مابین الحکومات میں صداقت کو عیب خیال کیا جاتا ہے.بڑے بڑے باحیثیت اور معزز لوگ فخر سے اپنے وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں جو اپنے دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے بولے تھے جنگ عالمگیر اوّل میں انگریزوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ جرمن لوگ مردوں کی چربی سے صابن تیار کرتے ہیں.خوب اس کا چرچا ہوااور تمام غیر جانبدار ملکوں نے بھی اس پر لعنت ملامت کی مگر بعد از جنگ خود اسی شخص نے جس نے یہ کہانی مشہور کی تھی تسلیم کیاکہ یہ کہانی ایک میس (Mess) میں جس میں افسر کھانا کھایا کرتے تھے محض پراپیگنڈا کی خاطر میں نے بنا کر مشہور کی تھی.یہ بھی شدت سے پراپیگنڈا کیا گیا کہ جرمن لوگ جہازوں کو غرق کر کے ڈوبنے والے سپاہیوں پر گولیاں چلاتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جنگ کے بعد برطانوی بحری جہازوں کے ملازموں کی طرف سے ایک ڈھال جرمنی کے ملاّحوں کو بھجوائی گئی جس پر یہ عبارت کنندہ تھی کہ اس ہمدردانہ اور شریفانہ رویہ کی یادگار کے طور پر جو جنگ کے ایام میں ڈوبنے والے سمندریوں کی نسبت آپ نے ظاہر کیا یہ ڈھال آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے.اس کے مقابل پر جرمن والوں نے بھی وہ وہ جھوٹ بولے کہ جس کی حد نہیں.عالمگیر جنگِ اوّل میں تو ریڈیو نہ تھا وہاں کے اخبار نہ آتے تھے اس لئے اس کے بارہ میں مَیں کچھ کہہ نہیں سکتا.مگر اس جنگ میں ریڈیو کی وجہ سے میں نے خود کئی دفعہ وہاں کی خبریں سنی ہیں اورجاپان کی بھی.ان خبروں میں اس قدر افتراء اور جھوٹ سے کام لیا جاتا تھا کہ تعجب آتا تھا بسا اوقات جرمن ریڈیو پر ہندوستان کے بڑے بڑے فسادات اور شورشوں کا ذکر ہوتا تھا جس کا نام و نشان بھی ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا تھا
Page 25
ان خبروںکو سن کر شبہ ہوتاتھا کہ ہم کسی اور دنیا میںبس رہے ہیں یا جرمن زبان میں ہندوستان کسی اور ملک کا نام ہے میں نے بعض کتب پہلی عالمگیر جنگ کے بارہ میں پڑھی ہیں ان میں سیاسیات کے چوٹی کے افراد نے ایسی بےتکلفی سے اپنے جھوٹوں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں پڑھ کر انسان انگشت بد نداں رہ جاتا ہے.اس بے تکلف جھوٹ کے بارہ میں دو۲ میرے اپنے تجربے بھی ہیں.میں انگلستان گیا تو مذہبی کانفرس کے اس اجلاس میں جس میں خواجہ کمال الدین صاحب کی تقریر پڑھی گئی میں گیا ہی نہیں تھا شیخ یعقوب علی صاحب رپورٹر کے طور پر اس کے نوٹ لینے کے لیے گئے تھے ’’ڈیلی نیوز‘‘ اخبار جو لبرل پارٹی کا سب سے چوٹی کا اخبار تھا اور کئی لاکھ روزانہ چھپتا تھا اب اسے ایک دوسرے زبردست اخبار ’’ ڈیلی کرانیکل‘‘ میں ملا کر دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے اور اس کا نام’’ نیوز کرانیکل‘‘ رکھ دیا گیا ہے اس کا ایک ایڈیٹر خاص طور پر مجھے ملنے کے لئے آیاتھا پہلے بہت دیر تک چوہدری ظفراللہ خان صاحب سے حالات معلوم کرتا رہا اور پھر مجھے بھی ملا.اس اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی کہ خواجہ صاحب کا مضمون بہت دلچسپ تھا اور وہ اس قدر پسند کیا گیا کہ امام جماعت احمدیہ جن کا رنگ سیاہ ہے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے بڑے شوق سے اس کے نوٹ لے رہے تھے.عزیز مکرم چوہدری سر ظفر اللہ خان نے اس کے ایڈیٹر کو فون کیا کہ یہ تمہارے اخبار میں کیا چھپ گیا ہے.وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں نوٹ لینے کی کیا ضرورت تھی نوٹ لینے والا تو رپورٹرتھا مگر اس نے چوہدری صاحب کی آواز سن کر ہی شور مچا دیا اور معذرت کرنی شروع کر دی کہ مجھے خود بڑا افسوس ہے میں تو انہیں مل آیا ہوں وہ کیا کہتے ہوں گے.نوٹ رپورٹر کی طرف سے تھا اور دوسرے ایڈیٹر نے احتیاط نہیں کی کل اس کی تردید ہو جائے گی.آپ ان سے بھی میری طرف سے معذرت کر دیں چوہدری صاحب خوش خوش فون سے ہٹے اور مجھے آ کر بتایا.دوسرے دن کا پرچہ آیا تو اس میں یوں تردید چھپی تھی:.’’ افسوس ہے کہ امام جماعت احمدیہ کی نسبت یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ ان کا رنگ سیاہ ہے.ان کا رنگ سیاہ نہیں بلکہ ہاتھی دانت کے رنگ کے مشابہ ہے.‘‘ اسے پڑھ کر ہنسی کے مارے ہمارا برا حال ہوا کہ اس نے یہ کس امر کی تردید کی ہے.چوہدری صاحب نے پھر فون کیا اور کہا کہ جنابِ من! رنگ آپ کالے کی جگہ اس سے بھی زیادہ سیاہ لکھ دیتے اس کی پرواہ نہ تھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ لیکچر کی دلچسپی کی وجہ سے امام جماعت احمدیہ اس کے نوٹ لے رہے تھے یہ غلط ہونے کے علاوہ ہتک آمیز بات ہے.اس کے جواب میں ایڈیٹر نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا مجھے کالے کا لفظ دیکھ کر ایسا صد مہ ہوا تھا کہ میں نے آپ کی بات کو غور سے سنا ہی نہیں اور یہی سمجھا کہ آپ بھی اسی امر کی شکایت کرنے لگے ہیں.مگر مجھے
Page 26
افسوس ہے کہ ہمارے اخبار کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنی خبر کی تردید نہیں کیا کرتے.ایک دفعہ آپ کا لحاظ کر کے تردید کر دی اب دوسری بار تردید کریں تو اخبار کی سُبکی ہوتی ہے اس لئے معذوری ہے.مارننگ پوسٹ وہاں کے بہت بڑے پرچوں میں سے تھا کنسر ویٹو پارٹی سے تعلق تھا.سرا ڈوائر غالباً اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے.ان کے تعلقات چونکہ مجھ سے تھے اس لئے غالباً ان کے اشارہ پر یہ اخبار ہمارے معاملات میں بہت دلچسپی لیتا تھا.یہ اخبار بھی اب بند ہو کر ڈیلی ٹیلی گراف میں مدغم ہو گیا ہے.اس سے پہلے اس کا نامہ نگار جس دن ہم نے لنڈن پہنچنا تھا سٹیشن پر موجود تھا مگر اتفاقاً گاڑی لیٹ ہو گئی اور کئی گھنٹے دیر سے پہنچنے کی اطلاع سٹیشن پر کی گئی.جو لوگ استقبال کے لئے آئے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے اور ان کو بتا دیا گیا کہ ریلوے کی خبر ہے کہ گاڑی اتنے گھنٹے لیٹ ہے.لیکن اتفاق یہ ہوا کہ گاڑی دوسرے اندازہ سے کچھ وقت پہلے پہنچ گئی.نیّر صاحب نے اخباروں کے نمائندوں کو خبر دینے کی کوشش کی.کچھ اخباروں کو خبر دے سکے اور کچھ کے دفاتر سے کنکشن نہ مل سکا.مارننگ پوسٹ کو بھی اطلاع نہ ہوئی دوسرے دن سب اخباروں میں ہماری خبر چھپی لیکن مارننگ پوسٹ میں نہ چھپی.نیّر صاحب نے ان سے شکایت کی تو جواب دیا کہ ہمارے پرچہ کا اصول ہے کہ دوسرے پرچہ سے خبر نقل نہیں کیا کرتے.انہوں نے کہا اب میں بتا رہا ہوں اب خبر چھاپ دیں جواب ملا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مارننگ پوسٹ میں دوسرے اخباروں کی نسبت خبر ایک دن لیٹ چھپی ہے.بات آئی گئی ہوئی جب مذہبی کانفرنس ہوئی اور اس میں میرے لیکچر کا بھی اعلان ہوا تو مارننگ پوسٹ نے نہایت شاندار طور پر اعلان کیا کہ ’’ امام جماعت احمدیہ کا لنڈن میں ورود‘‘ اور ساتھ فوٹو بھی شائع کیا.پڑھنے والوں نے سمجھا ہو گا کہ شاید امام جماعت احمدیہ کہیں چلے گئے ہوںگے اور اب پھر لنڈن واپس آئے ہیں.بہر حال مہینہ کے بعد ہمیں دوبارہ لنڈن وارد کر دیا گیا محض اس لئے کہ لوگوں پر یہ اثر قائم رہے کہ مارننگ پوسٹ ہمیشہ تازہ واقعات پیش کیا کرتا ہے.یہ حالات ایسے درد ناک ہیں کہ حیرت آتی ہے کہ اب صداقت کا مفہوم کیا ہو گیا ہے.درحقیقت اس زمانہ میں پراپیگنڈا کو اوّل او ر صداقت کو دوسرا نمبر دے دیا گیا ہے جس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی.امانت کایہ حال ہے کہ جنگِ عالمگیر اوّل میں کئی حکومتیں دوسری حکومتوں کا وہ سونا جو ان کے پاس امانت رکھا گیا تھا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کھا گئیں.دنیا میں اس وقت یہ عجیب نظارہ نظر آتا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو اپنے آپ کو تہذیب کا علمبر دار قرار دیتی ہے جو حُریت اور آزادی کے بلند بانگ دعاوی کرتے ہوئے نہیں تھکتی دوسرے ملک میں جاتی اور صرف چند سال کے لئے کوئی علاقہ یا شہر ٹھیکے پرلیتی ہے مگر رفتہ رفتہ اس علاقے یا شہر پر مستقل قبضہ
Page 27
جمالیا جاتا ہے اور اس کو واپس کرنے کا نام تک نہیں لیا جاتا.ہندوستان میں برار اس کی مثال ہے سوسال کے ٹھیکے پر حیدر آباد دکن سے برار لیا گیا تھا لیکن سو سال کی بجائے سوا سو سال گذرنے کو آئے ہیں اور اس کے واپس کرنے کا نام تک نہیںلیا جاتا.نظام نے جب اس کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اسے کہا گیا کہ یا تو برار کی واپسی کا دعویٰ کرو اور تخت سے اتر جائو یا تخت پر قائم رہو اور برار کا ذکر چھوڑ دو.مرتا کیا نہ کرتا وہ خاموش ہو گیا.آخر پچھلی جنگ میں نظام کی عظیم الشان جنگی خدمات کودیکھتے ہوئے ان سے کہا گیا کہ ہم برار آپ کو واپس کرتے ہیں اس کے بدلہ میں آپ ہماری طرف یہ لکھ دیں کہ میں برار کو انتظام کی خاطر ہمیشہ کے لئے حکومتِ انگلشیہ کو دیتاہوں اور ہم مزید یہ رعایت کریں گے کہ عثمانیہ ولی عہد آئندہ شہزادۂ برار کہلائے گا.کس قدر تمسخر انگیز تجویز ہے.حید رآباد کا شہزادہ حیدرآباد کا شہزادہ کہلائے تو اس کی عزت نہیں ہوتی شہزادہ برار کہلائے تو اس کی عزت ہوتی ہے لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ.اِسی طرح اس قسم کے قبضوں کی مثال چین کے مختلف بندر گاہ ہیں.مصر بھی ایک مثال ہے.عراق، شام اور فلسطین بھی اس کی مثال ہیں.عراق، شام اور فلسطین کے لوگوں نے ترکوں سے بغاوت کی اور ان سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ ہم اس کے بدلہ میں تم کو آزاد کر دیں گے مگر اب ان کی طرف سے آزادی کا نام لیا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آزادہی ہیں ہم تو یہاں آپ کی خدمت کے لئے بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو یہ نہیں سمجھناچاہیے کہ آپ آزاد نہیں ہیں.اِسی طرح سینکڑوں ملک ہیں جو عارضی طور پر لئے گئے اور پھر ان پر مستقل طور پر قبضہ کر لیا گیا.اب ایران میں بھی ایسا ہی جھگڑا شروع ہورہا ہے جنگ کے خاتمہ کے بعد چھ ماہ کے اندر اندر اسے خالی کرنے کے اعلان کئے گئے تھے مگر اب روس وہاں کے تیل کے چشموں پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہے اور وہاں کے لوگوں میںبغاوت پھیلائی جا رہی ہے چنانچہ آئے دن ان علاقوں میں بغاوت ہو رہی ہے اور روسی اخباروں میں یہ شائع کرایا جا رہا ہے کہ ایران میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہاں حُریتِ ضمیر کو بری طرح کچلا جا رہا ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد کہا جائے گا کہ کسی ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ محض انسانیت کی حفاظت کے لئے روس اپنے اوپر یہ کمر توڑ دینے والا بوجھ اٹھانے لگا ہے کہ ایران کے اس حصہ کو اپنے قبضہ میں کرتا ہے.بلغاریہ اور رومانیہ کا بھی یہی حال ہونے والا ہے.گویا جو عیب افراد کو ذلیل کر دیا کرتا تھا اب حکومتوں کو اس پر فخر ہے.عِفّت.عفّت کا اب کوئی مفہوم ہی نہیں رہا.زمانہ سابق میں عفّت شکن چوری چھپے سب کام کیا کرتا تھا.اب علی الاعلان ہوتا ہے مسٹرس کا رکھنا ایک عام بات ہے اور ملک کے چوٹی کے افراد اور بڑے بڑے فلسفی یہ کام
Page 28
کرتے اور علی الاعلان کرتے ہیں.ایک بڑے ملک کے عوام الناس کے اختیارات کے علمبر دار لیڈر کے پاس دس بارہ سال سے ایک عورت رہتی ہے وہ کہتے ہیں وطن کی خدمت کے جذبات کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتا مگر اس عورت کو اپنے پاس رکھنے سے وطن کی خدمت میں کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا.ہٹلر کے مرنے کے بعد پتہ لگا ہے کہ اس کے پاس بھی ایک مسٹرس تھی اور اس سے دو بچے بھی تھے.مرنے سے چند دن پہلے اس سے اس نے شادی کی تاکہ بچے اس کے وارث ہو سکیں.(The New Encyclopedia Britanica Under word "wars") اب بھلا اس میں کیا لطف تھا کیوں نہ شادی ہی کر لی.مسولینی نے بھی ایک مسٹرس رکھی ہوئی تھی اس کی بیوی نے اس کے مرنے پر کہا کہ وہ اچھا آدمی تھا.کسی نے اس کی مسٹرس کا ذکر کیا تو کہا کہ اس چڑیل نے اس شریف آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیاتھا.اس چڑیل سے جو سلوک لوگوں نے کیا اچھا کیا.کنچنی کو عیب سمجھا جاتا ہے لیکن قہوہ خانوں میں شریف بن کر عورتوں کا عصمت فروشی کرنا ایک عام رواج ہے اور کوئی اسے برا نہیں سمجھتا.ایک معروف بادشاہ کو ایک عورت سے محبت تھی.اس کا خاوند موجود تھا وہ اکثر ان کے پاس آتی جاتی تھی.اور لوگ جانتے تھے کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں خود ایسی دعوتوں میں بھی وہ عورت شریک ہوتی رہی جن میںگرجا کا سب سے بڑا بشپ بھی شامل ہوا لیکن اس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جب بادشاہ نے اسے طلاق دلوا کر اپنے نکاح میں لانا چاہا تو تمام پادریوں نے شور مچادیا کہ دین کی سخت ہتک ہونے والی ہے.یہ وہ عفّت ہے جسے پہلے زمانہ کے لوگ اور قدیم صداقتوں پر ایمان لانے والے سمجھ ہی نہیں سکتے.انصاف کے اب کوئی معنے ہی نہیں رہے دنیا کا ۴/۳حصہ لوگوں نے غلام بنا رکھا ہے.امریکہ جو آزادی کا علمبر دار ہے وہاں کے اصل باشندے ریڈانڈینز تھے جو اب صرف چند ہزار باقی رہ گئے ہیں.آسٹریلیا میں بھی پرانے باشندوں کی آبادی تھی مگر وہ بھی مرمرا کر ختم ہو گئے ہیں صرف چند افراد ان میں سے باقی ہیں جن کو وہاں ذلیل ترین اور بے وارث بنا دیا گیا ہے افریقہ کے حبشی بھوکے مرتے ہیں لیکن ان کی زمینیںاور جائیدادیں لاکھ لاکھ ایکٹر کی شکل میں انگلستان کے نو ابوں کو دے دی گئی ہیں.ساؤتھ افریقہ کے سفید باشندے حبشیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے ان کے ملک میں دند نار ہے ہیں اور وہاں کی کانوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر نام یہ ہے کہ ہم دنیا کو سویلائزڈ کر رہے ہیں.ہم دنیا کو مہذہب بنانے کے لئے اپنے گھروں سے قربانی کر کے آگئے ہیں.اب تو خیر ہندوستان کی حالت بدل رہی ہے.آزادی اور حُریت کا سانس لوگ لینے لگے ہیں اور ملک اپنی آزادی کی حفاظت کے لئے قربانی کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے.مگر پہلے یہ حالت تھی کہ ایک گورا ہندوستانی کو ٹھوکروں سے مار دیتا تھا اور عدالت کہتی تھی
Page 29
کہ اس کی تِلّی پھٹ گئی ہے اور یہ کوئی نہ پوچھتا کہ اس غریب ہندوستانی کی تلّی پھاڑنے کا حق اسے کس نے دیا تھا اور وجہ کیا ہے کہ ہندوستانی جب بھی مرتا ہے تلّی پھٹنے سے مرتا ہے.اس بات پر بھی کوئی غور نہ کرتا کہ آخر یہ کون سا اتفاق ہے کہ گورے صرف اسی ہندوستانی کومارتے ہیں جس کی تلّی بڑی ہو.مگر الحمد للہ کہ اب ہندوستان آزادی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور یہ معاملات گذشتہ قصہ بن گئے ہیں.تجارتی ترقی کے لئے زبردست اقوام دوسری اقوام کی تجارت کو دباتی چلی جاتی ہیں.کہیں ایکسچینج کے دھوکے سے، کہیں اس بنا پر کہ تمہارا فائدہ ہی اسی میں ہے کہ صنعت و حرفت نہ کرو اور زراعت کرو، کبھی اپنے ملکی جہاز بنانے کی اجازت نہ دے کر، کبھی نا جائز مدد اپنے ہم قوموں کو دے کر، کبھی تجارتی جتھے بنا کر، غرض ہر رنگ میں انصاف کو کچلا جا رہاہے.علوم میں تغیر (۵)علوم تو اب ایسے بدلے ہیں کہ پرانے علوم کا کچھ باقی ہی نہیں رہا.فلسفہ کی شکل سو فیصدی بدل چکی ہے.سائنس۹۰ فیصد ی تبدیلی ہو چکی ہے.پہلے تاریخ کی بنیاد روایات پر ہوا کرتی تھی اب روایات کوکوئی پوچھتا ہی نہیں.اب تاریخ کی بنیاد یا اخبارات ہیں یا ڈائریاں یا خطوط ہیں اور پرانی تاریخ کے لئے آثار قدیمہ اوراتھنالوجی اور جیالوجی اور علم طبقات الارض کی تلاش کی جاتی ہے.علم ہیئت قریباً بالکل بدل چکا ہے.سورج اب سیدھا چلنے لگا ہے.زمین گھومنے لگ گئی ہے.نظامِ شمسی کی جگہ نظام ہائے شمسی نے لے لی اور نظام ہائے شمسی کی جگہ نظام ہائے نظام ہائے شمسی نے لے لی ہے.دنیا کا پھیلائو پہلے کروڑوں میل بتایا جاتا تھا اب دنیا چھتیس۳۶ ہزار روشنی کے سالوں کے پھیلائو تک جا پہنچی ہے.چھتیس ہزار روشنی کے سالوں کے معنے یہ ہیں کہ ۳۶ ہزار×۶۰×۶۰×۲۴×۳۶۰×ایک لاکھ چھیاسی ہزار اگر انسان صبح سے شام تک بھی ان اعداد کو گننے لگے اور ضرب درضرب شمار کرتا چلا جائے تو شام تک بھی ان اعداد کو ختم نہیں کر سکتا.طب نے بھی حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر لی ہے.جن باتوں کا پہلے وہم و گمان بھی نہ تھا اب روز مرّہ کا شغل بن گئی ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے زمانہ میں بھی اپریشن ہوتے تھے مگر شاذو نادر کے طور پر کبھی بقراط کا نام اپریشن کے سلسلہ میں آجاتا اور کبھی کسی اور سرجن کا.مگر اب ہر ملک اور ہر شہر میں وہ سرجن پائے جاتے ہیں جو پیٹ کو پھاڑتے اور پھر اسے سی دیتے ہیں گردوں کا اپریشن کرتے ہیں ناک، کان، آنکھ، حلق اور دوسرے اعضاء کے نقائص کا اپریشن کے ذریعہ علاج کرتے ہیں بلکہ اس جنگ میں تو اس حد تک حیرت انگیز ترقی کر لی گئی ہے کہ اس جنگ کے دوران میں دل کے اپریشن بھی کئے گئے ہیں دل کو کھرچا گیا ہے اور پھر اسے کھرچ کر اس کے اصل مقام پر رکھ دیا گیا ہے.
Page 30
ایسے آلات نکل آئے ہیں کہ جن کہ وجہ سے وہ مریض جن کے دل حرکت نہیں کر سکتے یا سخت کمزوری سے کرتے ہیں ان کی زندگی کے بھی سامان پیدا ہو گئے ہیں چنانچہ ان کو ان آلات میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو دوسری صورت میں گھنٹہ دو گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا اس طرح بعض دفعہ مہینوں اور سالوں ان آلات میں پڑا رہتا ہے اس کا دل حرکت کرتا رہتا ہے اور قانونِ قدرت کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اس دوران میں بیماری کو دور کرکے اسے اچھا کر دے.غرض پرانی کتب مذہب کے سوا اب داستان امیر حمزہ بن کر رہ گئی ہیں اور دنیا روز بروز کہیں سے کہیں چلی جا رہی ہے.(۶) اقتصادیات کی حالت بھی بالکل بدل گئی ہے.پہلے دنیا کی تمام تجارت بارٹر سسٹم پر چلتی تھی.لوگ ایک جگہ سے مال لیتے اور دوسری جگہ پہنچا دیتے وہاں سے اس کے بدلہ میں کوئی ایسی چیز لے لیتے جس کی انہیں ضرورت ہوتی تھی.پھر وہاں کا مال اٹھا کر تیسرے ملک میں لے جاتے اور اس ملک کی کوئی ایسی چیز اس مال کے تبادلہ میں لے لیتے جس کی انہیں احتیاج ہوا کرتی تھی اس طرح جنس کے بدلہ میںجنس دی جاتی اور اپنی اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کی جاتیں.اس ذریعہ سے ملک غریب نہیں ہوتے تھے کیونکہ جتنا مال کسی ملک سے لیا جاتا تھا اتنا مال ہی اس کو دوسری شکل میں دے دیا جاتا تھا.مگر اب بارٹر سسٹم بالکل ختم ہو گیا ہے بنکنگ کا زور ہے اور بنک کی ہنڈی سے ہی ساری تجارت چلتی ہے اس کی وجہ سے غریب اور کمزور ممالک بالکل لوٹے جارہے ہیں.پھر افراد کی تجارت اب قریباً ختم ہے اب زیادہ تر کمپنیاں بنتی اور تجارتی کاروبار میں حصہ لیتی ہیں.چنانچہ غور کر کے دیکھ لو بڑی بڑی تجارتیں سب کمپنیوں کے ہاتھ میں ہیں جن کو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا.کمپنیوں سے اوپر ٹرسٹ بن گئے ہیں جو آپس میں معاہدہ کر کے ملک کی تجارت کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں.مثلاً دس پندرہ بڑی بڑی کمپنیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور وہ معاہدہ کر لیتی ہیں کہ ہم جو کچھ فروخت کریں گی ایک مقررہ قیمت پر کریں گی ایک دوسرے کا تجارتی رنگ میں مقابلہ نہیں کریں گی.اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ اسی قیمت پر چیز خریدیں خواہ وہ کس قدر ہی مہنگی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں انہیں ایک ہی قیمت بتائی جاتی ہے.یہ تو ملک کے بڑے بڑے تاجروں کا آپس میں سمجھوتہ ہوتا ہے جو ٹرسٹ سسٹم کہلاتا ہے اس سے مزید ترقی کر کے اب کارٹلز بن گئے ہیں یعنی مختلف ممالک کے بڑے بڑے تاجر یا مختلف ممالک کی بڑی بڑی کمپنیاں آپس میں کسی تجارت کے متعلق سمجھوتہ کرلیتی ہیں اور وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ فلاں فلاں چیز اس نرخ کے علاوہ اور کسی نرخ پر فروخت نہیں کی جائے گی.اس کے نتیجہ میں وہ تمام ممالک کی تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیںاورجو قیمت چاہتے ہیں لوگوں سے وصول
Page 31
کرتے ہیں.یہی کارٹلز ہیں جو جنگوں کاباعث ہیں کیونکہ بعض ممالک کی ساری کی ساری اجناس کارٹل سسٹم کے ماتحت تاجر خرید لیتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کی تجارت تباہ ہو جاتی ہے اور وہ لڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں.سورۂ زلزال میں بیان شدہ پیشگوئی کے واقعہ ہونے کا زمانہ یہ وہ زلزلہ ہے جو اس وقت دنیا پر آرہا ہے اور جس کا ہزارواں حصہ زلزلہ بھی اس سے پہلے کسی ایک وقت میںدنیا پر نہیں آیا.اب یہ زلزلہ جو ایک طرف مادی زمین پر آ رہا ہے اور دوسری طرف اہل زمین پر آ رہا ہے قیامت کے مشابہ نہیں تو اور کس کے مشابہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اِسی زلزلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس دن جب دنیا کفر میں ڈوب جائے گی اور دین بے کس ہو جائے گا خدا تعالیٰ پھر اس بیّنہ کے ذریعہ سے جو رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰہِ ہے ( یعنی اس کے مثیل کے ذریعہ سے) دنیا کو کفر سے نجات دے گا.اِذَا ظرف جملۂ محذوف ہے اور اس کا عامل ہے وَیَکُوْنُ کَذَا ثَانِیًا اِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَھَا.یعنی ایک دفعہ تو اہل کتاب اور مشرکین کو ہم اپنے رسول کے ذریعہ جو صحفِ مطہّرہ لے کر آیا ہے کفر سے نجات دے چکے ہیں اور ہم کہہ چکے ہیں کہ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ.رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ مگر مقدر یوں ہے کہ ہمارا یہ رسول ایک دفعہ پھر اس زمانہ میں لوگوں کو کفر سے نجات دے گا جب دنیا میں گمراہی اور تباہی اور خرابی پیدا ہوجائے گی اور زمین اور اہلِ زمین دونوں پر زلزلۂ عظیمہ آجائے گا.پہلے مفسرین نے اِذَا کا عامل تُحَدِّثُ کو بتایا ہے اور يَوْمَىِٕذٍ کو اِذَا کا بدل بتایا ہے اور مطلب یہ لیا ہے کہ زمین اپنی خبریں اس وقت بتائے گی جب زمین پر زلزلہ آئے گا.مگر میرے نزدیک تُحَدِّثُ عامل ہے يَوْمَىِٕذٍ کا اور یہ جملہ مستانفہ ہے یعنی تُحَدِّثُ سے ایک نیا مضمون شروع کیا گیا ہے کہ اس دن یہ بھی ہوگا کہ زمین اپنی اخبار بتائے گی.اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا پہلے مضمون کے تسلسل میں ہی بیان کیا گیا ہے یعنی ایسا ہی واقعہ ایک دفعہ پھر ہونے والا ہے.وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَاۙ۰۰۳ اور زمین اپنے بوجھ نکال (کر پھینک) دے گی.حلّ لُغات.اَثْقَالٌ.اَثْقَالٌ ثِقْلٌ کی جمع ہے اور ثِقْلٌ کے معنے بوجھ کے بھی ہوتے ہیں اور قیمتی شے کے بھی.ثِقْلٌ کے ایک معنے مَتَاعُ الْمُسَافِرِ وَ حَشْمُہٗ کے ہیں یعنی مسافر کا سامان اور اس کے خادم وغیرہ.جب سفر پر جاتے ہوئے کسی کے ساتھ سامان یا خادم وغیرہ ہوں تو عربی زبان میں ان کو اَثْقَال کہا جاتا ہے.اسی طرح
Page 32
لکھا ہے کُلُّ شَیْءٍ نَفِیْسٌ مَصُوْنٌ ہر اعلیٰ درجہ کی چیز جس کی حفاظت کی جائے اس کو عربی زبان میں ثِقْل کہتے ہیں مِنْہُ اِنِّیْ تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ الْقُرْاٰنُ وَ عِتْرَتِیْ.اسی کے مطابق حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں اپنے ثقلین چھوڑ رہا ہوں.اور وہ ثقلین کیا ہیں اَلْقُرْاٰنُ وَ عِتْرَتِیْ ایک ان میں سے قرآن ہے اور ایک میری عترت.پھر لکھا ہے اَصْلُ الثِّقْلِ مَا یَکُوْنُ مَعَ الْاِنْسَانِ مِـمَّا یُثْقِلُہٗ اصل میں جو چیز انسان پر بوجھ ڈالنے والی ہو اسے ثقل کہتے ہیں اور اَلْاَثْقَالُ کے معنے ہیں کُنُوْزُ الْاَرْضِ زمین کے خزانے.اَلْاَحْـمَالُ الثَّقِیْلَۃُ.بھاری بوجھ.مَوْتَاھَا.مدفون اشیاء.مُردے (اقرب) غرض ثِقْل کے معنے ہوئے.(۱)بوجھ (۲) وہ قیمتی شے جس کی حفاظت کی جائے (۳) زمین کا خزانہ.تفسیر.جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے ثِقْل کے معنے بوجھ کے بھی ہیں اور قیمتی شے کے بھی جس کی حفاظت کی جائے.ان معنوں کے رُو سے اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ زمین کے اثقال پھینکنے کے چھ معنے اوّل.زمین اپنے بوجھ اتار کر پھینک دے گی یعنی بادشاہتوں اور حکومت امراء کو جو غرباء پر ناقابلِ برداشت بوجھ ڈال رہے تھے نکال باہر کرے گی.سب سے بڑا بوجھ دنیا میں ناواجب اور ظالمانہ حکومت کا ہی ہوتا ہے اس سے بڑا بوجھ دنیا میں اور کوئی نہیں.ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کئے ہیں کہ یہ بوجھ اس طرح اتار کر پھینکا گیا ہے کہ اس کا ہزارواں حصہ بھی پہلی تاریخ میں نظر نہیں آتا.دنیا کے تمام ممالک بادشاہتوں کو توڑ رہے ہیں یا ان کو ناکارہ بنا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی پہلے زمانہ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی.پہلے زمانہ میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نظر نہیں آتا تھا جہاں بادشاہت نہ ہو سوائے چھوٹے چھوٹے قبائل کے کہ ان کے مالک بادشاہ نہیں کہلاتے تھے بلکہ رئیس کہلاتے تھے.مگر اب دنیا کے اکثر حصوں سے بادشاہتوں کو کلیۃً اڑا دیا گیا ہے.چنانچہ اگر ہم سر سری طور پر دنیا کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دیکھ جائیں تو یہ حقیقت ہم پر پورے طور پر واضح ہوجاتی ہے مثلاً امریکہ کو لے لو.نارتھ امریکہ میں کینیڈا پر فرانس کا بادشاہ حکومت کر رہا تھا اور سؤتھ امریکہ میں کچھ علاقوں پر پُرتگال کا بادشاہ حکومت کر رہا تھا اور کچھ علاقوں پر سپین کا بادشاہ حکومت کرتا تھا مگر اب ان تمام مقامات سے بادشاہتیں اُڑ گئی ہیں.اس کے بعد یورپ میں آئیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انگلستان کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.ناروے کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.سویڈن کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.ڈنمارک کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.ہالینڈ کا بادشاہ تھا اب بھی ہے بلجیئم کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.لیکن فرانس کا بادشاہ تھا اب نہیں.سپین کا بادشاہ تھا اب نہیں.پُرتگیزوںکا بادشاہ تھا اب نہیں.جرمنی کا بادشاہ تھا اب نہیں.اٹلی کا
Page 33
بادشاہ تھا اور اب بھی ہے (اس درس کے چھپنے سے پہلے وہ بھی نہیں رہا )ہنگری کا بادشاہ تھا اب نہیں.روس کا بادشاہ تھا اب نہیں.یونان کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.یوگوسلاویہ کا بادشاہ تھا اب نہیں.رومانیہ کا بادشاہ تھا اب نہیں.بلغاریہ کا بادشاہ تھااب نہیں.زیکو سلویکیا پہلے جرمنوں کے ماتحت تھا اب اتحادیوں کے قبضہ میں آیا ہے مگر وہاں بادشاہت نہیں.اس کے بعد ہم ایشیا کی طرف آتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ٹرکی کا بادشاہ تھا اب نہیں.ایران کا بادشاہ تھا اب بھی ہے.عراق میں بھی بادشاہت ہے شام اور فلسطین اور لبنان یہ علاقے بادشاہتوں کے ماتحت تھے مگر اب ان کے قبضہ سے نکل گئے ہیں.افغانستان میں نام کی بادشاہت باقی ہے.یہی حال ہندوستان کا ہے کہ اس کی بادشاہت بھی برائے نام ہے.چین کا بادشاہ ہوا کرتا تھا اب اڑ گیا ہے.کوریا کا بادشاہ تھا مگر اب اڑ گیا ہے.جاپان کا بادشاہ ہے مگر اب اتحادی اس کو اڑانے کی فکر میں ہیں.گویا دنیا میں تین چوتھائی بادشاہتیں اڑ چکی ہیں اور جو باقی ہیں وہ برائے نام ہیں جیسے انگلستان کا بادشاہ تو ہے مگر نام کا، اس کے اختیارات کچھ نہیں.پس فرماتا ہے زمین اس دن اپنے بوجھ اتار کر پھینک دے گی.یعنی بادشاہتوں اور حکومت امراء کو نکال باہر کرے گی اور اس طرح اس نا قابل برداشت بار کا خاتمہ ہو جائے گا جو غرباء پر پڑ رہا تھا.(۲) دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہیں کہ مولویوں،پادریوں اور پنڈتوں کے دبائو سے لوگ آزاد ہو جائیں گے.مولویوں کا دبائو بے شک حکومتی دبائو کی طرح زیادہ سخت نہیں تھا مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولویوں کے فتووں کی لوگوں کے دلوں میں عزت ہوتی تھی اور وہ بسا اوقات ان کے لئے بڑی بڑی قربانیاںکرنے کے لئے تیار ہوجاتے تھے مگر اب مولویوں کا دبائو بالکل اٹھ چکا ہے.یہی حال پنڈتوں کا ہے پنڈت جس جس رنگ میں کفارے دلواتے اور لوگوں کو گنگا اشنان کراتے تھے وہ اب جا تارہا ہے.اسی طرح پادریوں کا دبائو اب خاک میں مل چکا ہے.درحقیقت حقیقی دبائو پادریوں کا ہی تھا مولویوں اور پنڈتوں کو اس قسم کا اقتدار حاصل نہیں ہوا جس قسم کا اقتدار پادریوں کو حاصل ہو چکا ہے.اُن کو ہر جگہ حکومت حاصل تھی،وہ لوگوں کو سزا دینے کا اختیار رکھتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو قید یااُن کو قتل کر دینے کا اختیار بھی ان کو حاصل تھا اورانہوں نے عوام پر وہ حکومت کی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں مگر آج یہ سب چیزیں اڑائی جا رہی ہیں.(۳) تیسرے معنے اَثْقَالَ کے ظاہری زمین کے لحاظ سے یہ بنیں گے کہ زمین میں سے قسم قسم کی کانیں نکل آئیں گی.چنانچہ دیکھ لو آج کروڑوں کروڑ ٹن مٹی کا تیل جس کا پہلے زمانہ میں خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا زمین میں سے نکل رہا ہے اور ہر شہر، ہر قصبہ اور ہر گائوں میں اس سے کام لیا جا رہا ہے.تمام دنیا میں چکر لگا کر دیکھ لو ہر جگہ لیمپ
Page 34
مٹی کے تیل سے ہی جگمگاتے نظر آئیں گے سوائے ان مقامات کے جہاں بجلی کی روشنی مہیا کی جاتی ہے.پہلے زمانہ میں عام طور پر سرسوں کا تیل دئے میں ڈال کر روشنی حاصل کی جاتی تھی مگر اب کہیں بھی سرسوں کا تیل استعمال نہیں ہوتا سب جگہ مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے.اسی طرح کار خانے وغیرہ مٹی کے تیل سے چلتے ہیں.پٹرول جس سے موٹریں چلتی ہیں وہ بھی زمین میں سے ہی نکلتا ہے.پھر پتھر کا کوئلہ جس سے انجن،ریلیں اور مشینیں وغیرہ چلتی ہیں یہ بھی زمین میں دبا پڑا تھا اسی زمانہ میں اﷲ تعالیٰ نے اسے نکالا اور بڑی بڑی فیکٹریوں اور کار خانوںمیں کام آنے لگا.اسی طرح اور کئی قسم کی دھاتیں مثلاً یورینیم،پلاٹینم اور ریڈیم وغیرہ زمین میں چھپی پڑی تھیں اور لوگوں کو ان کا کچھ علم نہیں تھا.آج بہت سے کام ان کے ذریعہ سے چل رہے ہیں.اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ زمین نے آج اپنے بوجھ باہر نکال کر پھینک دیئے ہیں.(۴)آثار قدیمہ جو زمین میں چھپے پڑے تھے وہ بھی اثقال تھے اور امانت کا رنگ رکھتے تھے جسے زمین نے اپنے پیٹ میں دبایا ہوا تھا مگر آج یہ اثقال بھی باہرنکل رہے ہیں.بڑے بڑے شہر جو آج سے کئی کئی ہزار سال پہلے کے ہیں زمین میں سے نکل رہے ہیں کوئی شہر زمین میں نو۹۰ے فٹ نیچے مدفون تھا کوئی اَ۸۰سی فٹ نیچے تھا اور لوگوں کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ زمین جس پر وہ چل پھر رہے ہیں اس کے نیچے کتنے بڑے بڑے شہر چھپے ہوئے ہیں.آج محکمۂ آثارِ قدیمہ زمین کو کھود کر ان تمام شہروں کو باہر نکال رہا ہے اور کئی قسم کی پرانی تہذیبوں کا لوگوں کو علم حاصل ہو رہاہے.ان شہروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے مثلاً دس ہزار سال پہلے برتن کیسے تھے.کس قسم کے کپڑے لوگ پہنا کرتے تھے.ان کے مکانوں کی کیا شکلیں ہوا کرتی تھیں.سڑکوں کا کیسا انتظام تھا.ان کی سواریاں کس کس قسم کی ہوتی تھیں.ان کی گاڑیاں کیسی تھیں.ان کے چھپر کھٹ کیسے تھے.ان کے سامان کیسے تھے.یہ ساری چیزیں زمین میں سے نکال کر آج دنیا کے سامنے لائی جا رہی ہیں بلکہ اور تو اور مردے بھی باہر نکالے جا رہے ہیں اور عجائب گھروں میں لوگ ان کا تماشہ دیکھتے ہیں.غرض زمین کے نیچے جو چیزیں دبی ہوئی تھیں زمین نے ان کا بوجھ محسوس کیا اور اس نے ان تمام چیزوں کو باہر نکال کر کہہ دیا کہ لو میاں.عطائے تو بہ لقائے تو (۵) اگر ارض سے اہل ارض مراد لئے جائیں تو اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَھَا کے یہ معنے ہوں گے کہ عیاشی،آزادی اور لامذہبی وغیرہ کے وہ خیالات جن کو پہلے زمانہ میں لوگ اپنے سینوں میں دبا کر رکھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان خیالات کو ظاہر کیا تو گُدی سے ہماری زبان کھینچ لی جائے گی علی الاعلان ظاہر کریں گے.ان کے
Page 35
متعلق کتابیں لکھیں گے اور لوگوں سے بحثیں کریں گے کہ صحیح خیالات یہی ہیں تمہیں بھی اپنے سابق خیالات میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے.تھوڑے ہی دن ہوئے سوویٹ روس کے متعلق میں نے ایک عجیب بات پڑھی.جس طرح عیسائی تثلیث کا عقیدہ رکھنے کے باوجودیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید کامل عیسائیت نے ہی پیش کی ہے اسی طرح سوویٹ روس نے بھی طریق تو کچھ اور اختیار کیا ہوا ہے لیکن اپنے کام کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے.اس کے ایک اخبار نے لکھا کہ لوگ ہمارے متعلق اعتراض کرتے ہیں کہ روس میں شادی کا دستور کم ہے گو حکومت کسی کو شادی کرنے سے روکتی نہیں اور اس لحاظ سے یہ اعتراض بالکل غلط ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے.لیکن اگر غور کیا جائے تو جتنی بدکاری شادی سے پھیلتی ہے اتنی مسٹرس رکھنے سے نہیں پھیلتی.اس نظریہ کو دیکھ کر حیریت آتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر مسٹرس رکھنا بد کاری نہیں تو وہ بدکاری کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں.یہی حال دوسرے ممالک کا ہے کہ علی الاعلان عیاشی، آزادی اور لا مذہبی وغیرہ کے خیالات لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں اور وہ باتیں جو پہلے سینوں میں چھپا کر رکھی جاتی تھیں اب الم نشرح ہونے لگ گئی ہیں.(۶) چھٹے معنے یہ ہیں کہ اس زمانہ میں سائنس کی ایجادات کثرت سے ہوں گی اور زمین اپنے چھپے ہوئے راز نکال کر رکھ دے گی.ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامت بھی اس زمانہ میں نمایاں طور پر پوری ہوئی ہے چنانچہ ہر سال حیرت انگیز طور پر کئی قسم کی ایجادات ہوجاتی ہیں اور یہ سلسلہ برابر بڑھتا چلا جارہا ہے درحقیقت سائنس نام ہے زمین کے اثرات کے کیمیاوی نتائج کا.اور یہ کیمیاوی نتائج وہ اَثْقَال ہیں جو زمین میں مخفی تھے.اﷲ تعالیٰ نے اس زمانہ میں سائنس کی بکثرت ایجادات کے ذریعہ ان اَثْقَالکو نکال کر رکھ دیا ہے اور کوئی سال ایسا نہیں گذرتا جس میں قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت ظاہر نہ ہوتی ہو کہ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا.وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَاۚ۰۰۴ اور انسان کہہ اٹھے گا کہ اسے کیا ہوگیا ہے.تفسیر.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اپنے اَثْقَال کو نکال باہر کرے گی یہاں تک کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان حیرت سے کہہ اٹھے گا کہ مَالَھَا.اسے کیا ہوگیا ہے اس دنیا میں کیا کچھ راز پوشیدہ تھے جو ظاہر ہورہے ہیں اور کیا کیا چیزیں مخفی تھیں جن کو زمین اگل رہی ہے.
Page 36
دوسرے معنے یہ ہوسکتے ہیں کہ اَلْاِنْسَانُ سے ہر انسان مراد نہ ہو بلکہ کامل انسان مراد ہو.اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ کامل انسان دنیا کی عریانی اور لامذہبیّت کی حالت دیکھ کر کہے گا کہ اس دنیا کو کیا ہوگیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ سے اس قدر دور چلی گئی ہے.يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَاۙ۰۰۵ اس دن وہ اپنی (ساری ہی پوشیدہ) خبریں بیان کردے گی.تفسیر.یہ نیا مضمون بھی ہوسکتا ہے اور اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا کی تشریح بھی ہوسکتا ہے.نئے مضمون کے لحاظ سے میرے نزدیک اس کے یہ معنے ہیں کہ پیدائش زمین کے بارہ میں اس سے پہلے دنیا کو ایک مجمل اور ناقص علم حاصل ہوگا مگر فرماتا ہے اس زمانہ میں علم سائنس جیالوجی کی شکل میں اس قدر ترقی کرجائے گا کہ زمین کی بناوٹ اور شعاعوں اور لہروں وغیرہ کے ذریعہ سے زمین کی پیدائش کے مسئلہ پر بہت کچھ روشنی پڑنے لگے گی گویا اَخْبَارَهَا سے مراد یہ ہے کہ زمین اپنی حقیقت اور کیفیت پیدائش کے بارہ میں بہت کچھ باتیں بتانے لگ جائے گی.یہ اس لئے فرمایا کہ علم جیالوجی کا بڑا مدار خود مٹی کی ماہیت اور اس کے رنگوں اور اس کی تہوں پر ہے.یہ نہیں کہ کسی اور ذریعہ سے وہ ان معلومات کو حاصل کرتے ہیں بلکہ علم جیالوجی کے ماہرین مٹی کا رنگ دیکھ کر بتادیتے ہیں کہ اس اس قسم کے تغیرات زمین پر گذرے ہیں اس کی تہوں سے اندازہ لگا کر بتادیتے ہیں کہ اس تہہ پر یہ شکل ہے اور اس تہہ پر یہ شکل ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فلاں تغیر واقعہ ہوا اور پھر فلاں تغیر پیدا ہوا.اسی طرح مٹیوں کے رنگوں اور ان کی بوئوں سے اب کانوں وغیرہ کے پتہ لگانے کا علم نکل آیا ہے.اس علم کے ماہر انجینئر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاتے ہیں اور پتھروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتے یا زمین کو سونگھتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کہ یہاں فلاں قسم کی کانیں دفن ہیں.اسی طرح بجلی کی رَو کے ذریعہ سے کانوں کی اقسام اور ان کی گہرائیوں کا پتہ لیا جاتا ہے.یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین میں کس چیز کی کان ہے.لوہے کی ہے یا پیتل کی ہے اور پھر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سوگز نیچے ہے یا دو سو گز نیچے ہے یا چار سو گز نیچے ہے.غرض اس ذریعہ سے زمین اپنی خبریں بتارہی ہے.وہ زمین جوپہلے گونگی تھی اب کلام کرنے لگ گئی ہے.عام لوگ گذرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ زمین خاموش ہے وہ کچھ کہہ نہیں رہی.لیکن ایک انجنیئر گذرتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ زمین اسے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے مٹی کا تیل ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ
Page 37
اسّی۸۰ گز نیچے ہے یا یہ بتارہی ہوتی ہے میرے نیچے سونے کی کان ہے اور یہ بھی بتارہی ہوتی ہے کہ وہ سونے کی کان اتنی دور ہے یا یہ بتارہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے پتھر کا کوئلہ ہے اور یہ بھی بتارہی ہوتی ہے کہ وہ پتھر کا کوئلہ اتنی دور ہے.اسی طرح بتارہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے یورینیم یا پلاٹینم یا فلاں دھات ہے اور یہ بھی بتارہی ہوتی ہے کہ یہ دھاتیں اتنی گہرائیوں پر ہیں.اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا کے نیچے جو یہ معنے بتائے گئے تھے کہ لوگ اپنے گندے خیالات بیان کرنے لگ جائیں گے ان کے لحاظ سے اس آیت کہ یہ معنے بھی ہوں گے کہ نہ صرف لوگوں کے دبے ہوئے خیالات اس زمانہ میں ظاہر ہونے لگ جائیں گے بلکہ اہل زمین اپنے ان عیوب کو الم نشرح کرنے میں لذت محسوس کریں گے یا دوسروں کے عیوب شائع کرنے میں انہیں خاص لطف محسوس ہوگا اور وہ انتہائی دلچسپی کے ساتھ اس کام میں حصہ لیں گے.چنانچہ تمام یورپ، امریکہ بلکہ ایشیائی ممالک میں بھی آج کل ایسے اخبارات نکلتے ہیں جن کوسوسائٹی گاسپ کہا جاتا ہے.یہ اخبار اس کثرت سے دنیا میں شائع ہونے لگ گئے ہیں اور اس طرح مزے لے لے کر ان کو پڑھا جاتا ہے کہ حیرت آتی ہے.ان اخبارات کو چلانے والے بھی لاکھوں روپیہ اس بات پر خرچ کردیتے ہیں کہ انہیں کسی بڑے شخص کے راز معلوم ہوجائیں.خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور پھر جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو ان رازوں کو اخبارات کے ذریعہ شائع کیا جاتا ہے اور دنیا میں ان کی خوب تشہیر کی جاتی ہے.اس کے علاوہ لوگ خود اپنے شہوانی جذبات کی نسبت بالتفصیل کتب لکھنے لگ گئے ہیں صرف قانون کی زد سے بچنے کے لئے ان کتابوں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتابیں صرف ڈاکٹروں اور فلاسفروں کے لئے لکھی گئی ہیں عام لوگوں کے لئے نہیں.تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ان کتابوں کی اشاعت محض علمی اغراض کے ماتحت کی جارہی ہے کوئی نفسانی خواہش ان کتب کی اشاعت کی محرک نہیں ہے.اس قسم کی بعض کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں.مثلاً امریکہ کے بارہ ڈاکٹروں نے آپس میں قسمیں کھاکر عہد کیا کہ علم شہوت چونکہ ایک مخفی علم ہے اور لوگوں کو اس کی تمام تفاصیل کا صحیح طور پر علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی قسم کے دھوکے لگ جاتے ہیں اس لئے ہم اس قسم کی تمام باتوں کو بغیر کسی حجاب کے ظاہر کریں گے.چنانچہ انہوں نے بارہ کتابیں لکھی ہیں جن میں اپنے جذبات کو انہوں نے ننگے الفاظ میں بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب ہم میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے یوں جذبات ہوتے ہیں، ہم اس طرح حرکات کرتے ہیں اور اس اس رنگ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں.ان بارہ کتابوں میں سے ایک کتاب میں نے بھی پڑھی ہے.زمین کے اپنے اخبار بیان کرنے سے مراد ایک حدیث بھی ان معنوں کی تصدیق کرتی ہے.میں
Page 38
سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث اسی زمانہ کے بارہ میں ہے.احمد، ترمذی اور نسائی نے روایت کی ہے (گو الفاظ روایت احمد کے ہیں) کہ عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللہِ صلی اللہ علیہ وسلم ھٰذِہِ الْاٰیَۃَ يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُھَا قَالُوْا اَللہُ وَ رَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَھَا اَنْ تَشْھَدَ عَلٰی کُلِّ عَبْدٍ وَّ اَمَۃٍ بِـمَا عَـمِلَ عَلٰی ظَھْرِہَا اَنْ تَقُوْلَ عَـمِلَ کَذَا وَ کَذَا یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا فَھٰذِہٖ اَخْبَارُھَا.( مسند احمد، مسند ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ) یعنی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا پھر آپ نے فرمایا اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُھَا اے میرے صحابہؓ! کیا تم جانتے ہو کہ اس کی اخبار کیا ہیں؟ قَالُوْا اَللہُ وَ رَسُوْلُہٗ اَعْلَمُ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں.قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَھَا اَنْ تَشْھَدَ عَلٰی کُلِّ عَبْدٍ وَّ اَمَۃٍ بِـمَا عَـمِلَ عَلٰی ظَھْرِہَا.اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہرانسان یعنی ہر مرد اور عورت کے متعلق یہ بیان کرے گی کہ اس نے کیا کیا ہے.اَنْ تَقُوْلَ عَـمِلَ کَذَا وَ کَذَا یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا.وہ یہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیا ہے اور فلاں دن یہ کام کیا.چونکہ اس آنے والے دن کے بارہ میں محدثین کو علم نہ تھا انہوں نے اسے قیامت پر لگایا ہے حالانکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اسی زمانہ کے متعلق ہے.اسی زمانہ میں اس قسم کے اخبارات شائع ہورہے ہیں جن میں لوگوں کے تمام عیوب بیان کئے جاتے ہیں اور لوگ ان اخبارات کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں.لنڈن کا ایک اخبار تھا جس کی نسبت میں نے سنا ہے کہ ایک لاکھ چھپتا ہے اور صبح صبح چوری چھپے ہر شخص خواہ وہ اعلیٰ حیثیت کا مالک ہو یا ادنیٰ حیثیت کا اسے مزے لے لے کر پڑھتا تھا.اس اخبار میں یہی لکھا ہوتا تھا کہ فلاں کی بیوی نے یہ کیا اور فلاں کی بیٹی نے یہ کیا.حتی کہ بعض جگہ شاہی خاندان کے متعلق بھی اشارے ہوتے تھے کہ آج صبح فلاں کو ایک بند گاڑی میں فلاں مکان کے دروازہ کے پاس دیکھا گیا ہم حیران ہیں کہ وہ وہاں کیوں گئے؟ اور کیوں ان کی گاڑی اس دروازہ پر کھڑی دیکھی گئی؟ میں سمجھتا ہوںحدیث میں اسی طرف اشارہ ہے.مفسرین نے اسے غلطی سے قیامت پر چسپاں کردیا ہے حالانکہ قیامت کے ذکر میں قرآن کریم میں یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ اس روز زمین بھی کلام کرے گی.یہ تو آتا ہے کہ ہاتھ بولیں گے یا پائوں بولیں گے اور وہ انسان کے خلاف شہادت دیں گے مگر یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ اس روز زمین بھی بولے گی.لیکن مسیح موعودؑ کے زمانہ کے متعلق بالوضاحت احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت زمین کلام کرے گی.چنانچہ حدیث میں آتا ہے مسیح موعودؑ کے زمانہ میں وہ پتھر جس کے پیچھے کافر چھپا ہوا ہوگا بول اٹھے گا اور کہے گا اے نبی اللہ یہ کافر چھپا ہوا ہے.(بخاری کتاب الجھاد و السیر باب قتال الیھود) غرض زمین کے بولنے کا حدیثوں
Page 39
میں جہاں بھی ذکر آتا ہے مسیح موعودؑ کے زمانہ کے متعلق ہے اور قرآن کریم میں جہاں قیامت کے دن شہادت دینے کا ذکر آتا ہے وہاں ہاتھوں اور پائوں کے بولنے کا تو ذکر آتا ہے مگر زمین کا نہیں.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت موجودہ زمانہ کے متعلق ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خبر دی گئی ہے کہ لوگ اپنے گند اخباروں میں ظاہر کریں گے.کتابوں اور ڈائریوں میں ان کو شائع کریں گے اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سرانجام دیا ہے گویا جن امور کو لوگ پہلے چھپایا کرتے تھے ان کو مزے لے لے کر بیان کریں گے اور شرم اور حیا کا مفہوم اس زمانہ میں بالکل بدل جائے گا.چنانچہ یہ اخبارہر بڑے مرد اور عورت کے پیچھے آدمی لگاتے ہیں اور ان کے مخفی حالات اخباروں میں چھاپتے اور ان کی بِکری سے لاکھوں روپے کماتے ہیں.بعض ادنیٰ اخبار بلیک میلنگ سے روپے کماتے ہیں.اسی طرح عورتیں، شریف کہلانے والی عورتیں بڑے بڑے معزز اور بارسوخ خاندانوں کی عورتیں ڈائریاں لکھتی ہیں جن میں نہایت بے حیائی سے اپنی کرتوتیں بیان کرتی ہیں اور پھر وہ ڈائریاں ہزاروں کی تعداد میں چھپتی اور لوگوں کے مطالعہ میں آتی ہیں.غرض ایک اندھیر ہے جو مچ رہا ہے اور ایک زلزلۂ عظیمہ ہے جو دنیا پر آیا ہوا ہے.گذشتہ تاریخ پر غور کرکے دیکھ لو اس کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملے گی.یہی وہ زمانہ ہے جس میں یہ زلزلۂ عظیمہ آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہوئی کہ يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا.بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَاؕ۰۰۶ اس لئے کہ تیرے رب نے اس (زمین) کے حق میں وحی کر چھوڑی ہے.حلّ لُغات.اوحٰی.اَوْحٰی اِلَیْہِ اِیْـحَاءً کے معنے ہوتے ہیں بَعَثَہٗ.اس کو کسی مقصد کے لئے کھڑا کیا اور اَوْحٰی بِکَذَا کے معنے ہیں اَلْھَمَہٗ بِہٖ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالی.اور وَحٰی بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ وَحٰی اِلیہِ (یَـحِیْ وَحْیًا) کے معنے ہیں اَشَارَ اس نے اشارہ کیا.اَرْسلَ اِلَیْہِ رَسُوْلًا اس کی طرف پیغامبربھیجا.اور وَحَی اللہُ فِیْ قَلْبِہٖ کے معنے بھی اَلْھَمَہٗ کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں فلاں بات ڈالی اور وَحَی اِلٰی فُلَانٍ اَلْکَلَامَ کے معنے ہیں کَلَّمَہٗ خَفِیًّا اس کے ساتھ دوسروں سے علیحدہ ہوکر مخفی رنگ میں بات کی.وَفِی الْاَسَاسِ وَحَیْتُ اِلَیْہِ وَ اَوْحَیْتُ اِذَا کَلَّمْتَہٗ بِـمَا تُـخْفِیْہِ عَنْ غَیْرِہٖ.زمخشری کی کتاب اساس میں لکھا
Page 40
ہے کہ وَحَیْتُ اِلَیْہِ یا اَوْحَیْتُ اِلَیْہِ اس وقت بولتے ہیں جب تم کسی سے کوئی ایسی بات کرو جو تم دوسروں سے چھپانا چاہتے ہو.وَ فِی الْمِصْبَاحِ وَ بَعْضُ الْعَرَبِ یَقُوْلُ وَ حَیْتُ اِلَیْہِ وَ وَحَیْتُ لَہٗ وَ اَوْحَیْتُ اِلَیْہِ وَ لَہٗ.اور مصباح میں لکھا ہے کہ بعض عرب صرف وَحَیْتُ اِلَیْہِ اوراَوْحَیْتُ اِلَیْہِ ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ وَحَیْتُ لَہٗ اور اَوْحَیْتُ لَہٗبھی استعمال کرتے ہیں(اقرب).مجمع البحار میں لکھا ہے وَیَقَعُ الْوَحْیُ عَلَی الْکِتَابَۃِ کہ وحی کا لفظ کتابت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اگر ہم وحی کا لفظ بولیں تو اس کے صرف یہی معنے نہیں ہوں گے کہ کوئی بات کی بلکہ یہ بھی معنے ہوں گے کہ کوئی بات لکھ دی.وَالْاِشَارَۃِ اور اگر اشارہ سے بات کی جائے تو اس کے لئے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے.والرسالۃ اسی طرح کسی کی معرفت اگر کوئی پیغام بھیجا جائے تو اسے بھی وحی کہہ دیتے ہیں.وَالْاِلْھَامِ الہام کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.وَالْکَلَامِ الْـخَفِیِّ اور وحی کا لفظ کلام خفی پر بھی دلالت کرتا ہے.لیکن مجمع البحار والے اس کے ساتھ یہ تصریح کرتے ہیں کہ اس کا صلہ ہمیشہ الٰی آتا ہے.ان کے نزدیک عربی زبان میں اس لفظ کو یوں ہی استعمال کریں گے کہ وَحَیْتُ اِلَیْہِ الْکَلَامَ وَاَوْحَیْتُ.پھر لکھتے ہیں’’ وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰى‘‘ وَحْیُ اِعْلَامٍ لَا اِلْھَامٍ لِقَوْلِہٖ تَعَالٰی ’’اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ‘‘.اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰى یہ وحیٔ اعلام ہے نہ کہ وحیٔ الہام.کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے یعنی لفظی وحی تھی دل کا خیال نہ تھا (علماء سابق اصطلاح میں دل کے خیال کو الہام کہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ وحی اور الہام میں فرق کرتے تھے حالانکہ یہ فرق ان کا خیالی تھا شریعت سے اس کی سند نہیں ملتی.بہرحال جب پرانے علماء کی کتب میں الہام کا لفظ استعمال ہو تو اس کے معنے اکثر دل میں خیال ڈالے جانے کے ہوتے ہیں).اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ : اَمَرْتُـھُمْ.یعنی قرآن کریم میں جو آتا ہے کہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی اس کے معنے یہ ہیں کہ میںنے ان کو حکم دیا.پھر لکھتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ (النحل:۶۹) تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی اس کے معنے یہ ہیں اَلْھَمَھَا اس کو الہام کیا ان کی طبیعت میں یہ خواہش پیدا کر دی.فَاَوْحٰی اِلَیْـھِمْ.اَوْمٰی.اور یہ جو قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ اَوْحٰی اِلَیْـھِمْ زکریا نے اپنے ساتھیوں کی طرف وحی کی اس کے معنے ہیں اَوْمٰی انہوں نے اشارہ کیا.وَقِیْلَ کَتَبَ بِیَدِہٖ فِی الْاَرْضِ(مجمع البحار).اور بعض نے کہا ہے کہ اس جگہ وحی کا لفظ بمعنی کتابت استعمال ہوا ہے اور آیت کے یہ معنے ہیں کہ انہوں نے لکھ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا.ان حوالجات سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے معنے (۱) کسی کام پر مبعوث کرنا (۲) دل میں بات ڈالنا (۳) اشارے سے بات سمجھانا (۴) کسی پیغامبر کی
Page 41
معرفت پیغام بھیجنا (۵) لکھنا (۶) دوسروں سے چھپا کر بات کرنا اور (۷) حکم دیناکے ہیں.تفسیر.قرآن مجید میں لفظ وحی کا صلہ قرآن کریم میں وحی کا لفظ اس مقام کے سوا پینسٹھ ۶۵ دفعہ استعمال ہوا ہے اور سب جگہ اِلٰی کا صلہ آیا ہے.پانچ مقامات اور ہیں جہاں یا تو یہ لفظ مجہولاً استعمال ہوا ہے یا حذفِ صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے.حذفِ صلہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں مُوْحٰی اِلَیْہِ کا ذکر نہیں کیا گیا.اس لئے ان مقامات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا.بہرحال ان سب استعمالات کی موجودگی میں جبکہ قرآن کریم میں پینسٹھ دفعہ یہ لفظ اِلٰی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اس امر کو دیکھ کر احادیث میں بھی جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اِلٰی کے ساتھ استعمال ہوا ہے لام کا صلہ استعمال نہیں کیا گیا.یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ بھی لَھَا سے یہ مراد نہیں کہ زمین کی طرف وحی کی بلکہ لام کے معنے فِیْ کے ہیں یعنی زمین کے حق میں وحی کی اور جس کی طرف وحی ہوئی اس کے ذکر کو چھوڑ دیا گیا ہے.اگر زمین کی طرف وحی کرنا مراد ہوتا تو محاورئہ قرآن و محاورئہ حدیث کو مدنظررکھتے ہوئے اس جگہ اَوْحٰی اِلَیْـھا آتا اَوْحٰی لَھَا نہ آتا.یہ بات ہر شخص جو قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے جانتا ہے کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس لئے گو یہاں مُوْحٰی اِلَیْہِ محذوف ہے اور یہ ذکرنہیں کیا گیا کہ وحی کس کو ہوئی.لیکن اس بات کا سمجھنا مشکل نہیں کہ اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ہی ذکر کیا جارہا ہے اور بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا کے معنے یہ ہیں کہ اَوْحَی اللہُ اِلٰی مُـحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَھَا.یعنی ان عظیم الشان تغیرات پر تمہیں کوئی استعجاب نہیں ہونا چاہیے.یہ سب تغیرات اس لئے ہوں گے کہ اس کے ان تغیرات کے متعلق پہلے سے قرآن کریم میںپیشگوئی موجود ہوگی.گویا یہ آیت زمانہ بعد نزول کے لوگوں کو مدّ ِنظر رکھ کر ہے.بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا اللہ تعالیٰ اس بارہ میں پہلے سے خبر دے چکا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ ایسا ضرور ہوکر رہے گا.پس چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعہ یہ خبر دے چکا ہے کہ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا.اہل زمین اپنے گند ظاہر کردیں گے اس لئے اب یہ اٹل فیصلہ ہے اور خدائی تقدیر کاہاتھ اس کو بہرحال پورا کرکے رہے گا.کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کی اپنی وحی کے ذریعہ خبر دے دے اور اسے کسی مامور کی سچائی کی علامت قرار دے دے تو پھر وہ کبھی ٹلا نہیں کرتی.بہت سے خلاف ِ فطرت جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان ان کی شناعت پر غور کرتا ہے تو اس کا دل اسے ملامت کرتا اور وہ ان کے ارتکاب سے رک جاتا ہے.مگر فرماتا ہے ان افعال سے زمانہ کبھی نہیں رکے گا کیوںکہ ہمارے علم غیب نے اس زمانہ کے لوگوں کے انجام عمل کا احاطہ کیا ہواہے.اگر اس کے خلاف انہوں نے کرنا ہوتا تو ہم وہ بات بتادیتے مگر آئندہ زمانہ کی نسلیں ہمیں ان اعمال پر تلی ہوئی نظر آرہی ہیں.پس بے شک ان حالات کی خبریں سن سن کر تمہیں
Page 42
یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہوگی اور تم حیران ہوگے کہ ایسا کس طرح ہوگا.یہ تو فطرت کے خلاف باتیں ہیں اور جب لوگ ان کاارتکاب کرنے لگیں گے تو ان کی فطرت خودبخود مقابلہ کرے گی اور انہیں سختی سے اس گناہ کے سیلاب میں بہنے سے روک لے گی.مگر یہ درست نہیں وہ کبھی نہیں رکیں گے کیونکہ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا یہ خبر قرآن کریم میں آچکی ہے اور قرآن عالم الغیب ہستی کی کتاب ہے وہ وہی کچھ آئندہ زمانہ کے متعلق لکھتا ہے جو ہوناہوتا ہے.اگر لوگوں نے ان حالات سے پھر جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے یہ امر بھی مخفی نہ رہتا اور وہ اس کا حال بھی بیان کردیتا.بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا میں اَوْحٰى کا صلہ بیان نہ کرنے کی حکمت اَوْحٰى کا صلہ ہمیشہ اِلٰى استعمال ہوتا ہے مگر اس جگہ اَوْحٰى کے بعد لام استعمال کیا گیا ہے.ایسا کیوں ہوا ہے؟ مفسرین نے اس کا یہ جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ بعض قبائل عرب میں اِلٰى کی بجائے لام بھی بطور صلہ استعمال ہوتا ہے جیسے وَحَیْتُ اِلَیْہِ اور اَوْحَیْتُ اِلَیْہِ کی بجائے بعض عرب وَحَیْتُ لَہٗ اور اَوْحَیْتُ لَہٗ بھی استعمال کرلیتے ہیں.(فتح القدیر سورۃ زلزال زیر آیت بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا) مگر ہم اس توجیہ کو درست تسلیم نہیں کرسکتے.قرآن کریم میںپینسٹھ جگہ وحی کا لفظ آیا ہے اور ہر جگہ اِلٰى کا صلہ ہی استعمال ہوا ہے اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ یہاں اِلٰى کی بجائے لام کے صلہ کا جواز نکالا جائے.بعض اور مفسرین نے اس جواب کی غلطی کو محسوس کیا ہے اور انہوں نے اس کے معنے یہ کئے ہیں کہ اَوْحٰى اِلَى الْمَلٰٓىِٕكَةِ لَھَا یعنی جس کی طرف وحی کی گئی ہے اس کے ذکر کو محذوف تسلیم کیا ہے.یہ توجیہ درست ہے لیکن میرے نزدیک یہاں اَوْحٰى اِلَى الْمَلٰٓىِٕكَةِ مراد نہیں بلکہ اَوْحٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مراد ہے اور معنے یہ ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ یہ خبریں دے رکھی ہیں اس لئے اب ایسا ضرور ہوکر رہے گا.یہ بات رک نہیں سکتی.ہم نے اپنی وحی میں یہ خبر دے دی ہے کہ اس زمانہ میں جب مسیح موعود آئے گا اور جو ہمارے رسول کی دوسری بعثت کا زمانہ ہوگا یہ علامات رونما ہوں گی.پس بے شک اور باتیں ٹل سکتی ہیں مگر یہ علامت کبھی ٹل نہیں سکتی کیونکہ جس چیز کو کسی مامور کی شناخت کے متعلق بطور علامت قرار دے دیا جائے وہ کبھی ٹلا نہیں کرتی.اس اصول کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنی کتب میں بیان فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ بے شک انذاری خبریں ٹل جایا کرتی ہیں مگر وہ انذاری خبریں جو اللہ تعالیٰ کے کسی مامور کی علامت کے طور پر بیان ہوئی ہوں کبھی نہیں ٹلتیں.بلکہ وہ اسی طرح پوری ہوتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے خیر کے امور پورے ہوتے ہیں.آیت بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا کی تشریح مسیح موعود کی زبان سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اس آیت کے ایک اور معنے بھی فرمایا کرتے تھے جو میں نے خود آپ کی زبان سے سنے ہیں.آپ فرماتے تھے
Page 43
بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا سے مراد یہ ہے کہ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى اِلٰى اِمَامِ الزَّمَانِ یعنی جس کی طرف وحی کی گئی ہے اس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور امام الزمان بھی جس کی طرف اس وقت کہ ان پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا وقت قریب ہوگا دوبارہ وحی کی جائے گی.آپ کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں مختلف قسم کے زلازل کے ظہور کے متعلق جو خبریں آپ کو دی گئی تھیں ان کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے.چونکہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ زلازل پہلے کیوں نہیں آئیں گے اس وقت کیوں آئیں گے جب مسیح موعودؑ کی بعثت ہوگی؟ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ زلازل اس وقت اس لئے آئیں گے کہ یہ اس کی سچائی کی علامت قرار دیئے گئے ہیں.چنانچہ جب مسیح موعود آئے گا اور اس علامت کے ظہور کا زمانہ قریب آجائے گا اللہ تعالیٰ پھر اپنا الہام نازل کرکے مسیح موعودؑ کو خبر دے گا کہ لو وہ زمانہ اب آگیا جس کی ہم قرآن کریم میں خبر دے چکے تھے.اس طرح تکرار الہام نہ صرف زمانۂ زلازل کے قرب پر دلالت کرے گا بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہوگا کہ یہی وہ مامور ہے جس کی سچائی ثابت کرنے کے لئے زلازل کا ظہور ہورہا ہے.پس اس وحی کے بعد دنیا میں زلازل کا سلسلہ اس لئے شروع ہوگا تا کہ یہ زلازل امامِ زمان کی سچائی کا ثبوت قرار پائیں اور دنیا غور کرے کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کا مامور نہیں تو آخر وجہ کیا ہے کہ جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ بڑے بڑے زلازل سے دنیا کا نقشہ پلٹنے والا ہے اس نے ان تاریک دنوں کی خبریں دیں اور پھر وہ حرف بحرف پوری ہوگئیں.غرض مُوْحٰی اِلَیْہِ دونوں ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی اوّل کے لحاظ سے اور مسیح موعودؑ وحی ثانی کے لحاظ سے.اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا کی پہلی وحی چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور درحقیقت آپ کی صداقت کے اظہار کے لئے ہی قیامت تک تمام نشانات کا ظہور ہوگا اور جو شخص بھی لوگوں کی ہدایت کے لئے کھڑا ہوگا وہ بہرحال آپ کا غلام ہوگا.اس لئے اوّل مصداق اس آیت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زلزلۂ عظیمہ کے اظہار کو روکے رکھا جب تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر دوبارہ الہام نازل نہ ہوا تا وہ بات پوری ہو جو لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ.رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ میں بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مثیل کے ذریعہ ایک اور زمانہ میں بھی ظاہر ہوں گے اور دوبارہ لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نجات دیں گے اس لئے اس آیت کے دوسرے مصداق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا تھا کہ یہ زلزلہ اس
Page 44
وقت تک نہیں آئے گا جب تک دوبارہ اس شخص پر وحی نازل نہ ہوجائے جو مثیل ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جس کی سچائی کے لئے اسے علامت قرار دیا گیا ہے.پس مُوْحٰی اِلَیْہِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی.اور بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا میں ان دونوں وحیوں کی طرف اشارہ ہے.وحی اوّل کی طرف اس لئے کہ وہ ہادی ہے اور وحی ثانی کی طرف اس لئے کہ وہ مثال کے رنگ میں وہی جلوہ دوبارہ ظاہر کرنے والی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظاہر ہوا.وحی کی تشریح علمائے سلف کے نزدیک وحی کیا شے ہے اس بارہ میں لغت کے حوالہ جات تو اوپر لکھے جاچکے ہیں اب میں اس کی حقیقت شرعی کے متعلق کچھ روشنی ڈالنا چاہتاہوں.اس بارہ میں بہترین اجمالی حوالہ پرانے علماء کے خیالات کے متعلق ایک لغت ہی کی کتاب سے ملتا ہے اور وہ لغات قرآن کی کتاب مفرداتِ راغب ہے.اس میں لکھا ہے اَصْلُ الْوَحْیِ: اَلْاِشَارَۃُ السَّـرِیْعَۃُ وحی کے اصل معنے اشارہ کے ہوتے ہیں مگر ایسا اشارہ جو جلدی سے کیاجائے.اشارے دو طرح ہوتے ہیں ایک تو آہستگی اور آرام سے کیاجاتا ہے مگر ایک ایسی جلدی سے کیا جاتا ہے کہ وہ شخص تو سمجھ جاتا ہے جس کو ہم نے اشارہ کیا ہوتا ہے مگر دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے.پس مفردات والے کہتے ہیں کہ وحی کے حقیقی معنے اَلْاِشَارَۃُ السَّـرِیْعَۃُ کے ہیں.اشارۃ سریعہ میں درحقیقت اخفاء شامل ہوتا ہے.چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بات کرتے وقت جلدی سے آنکھ مارجاتے ہیں یا انگلی سے اشارہ کردیتے ہیں یا سر کو کسی خاص طریق پر حرکت دے دیتے ہیں جس سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مقصد کا اظہار اس شخص پر کردیں جسے بات بتانا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہمارے اشارہ کا علم نہ ہو.گویا محض اشارہ اور اشارۃ سریعہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اشارے سے تو صرف اتنی غرض ہوتی ہے کہ دوسرے شخص کو کوئی بات سمجھادی جائے خواہ اس کا کسی اور کو علم ہو یانہ ہو.مگر اشارۃ سریعہ سے یہ غرض ہوتی ہے کہ اشارہ بھی ہوجائے اور مخاطب کے سوا دوسروں کو اس کا علم بھی نہ ہو.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی حقیقۃ الوحی اور بعض دوسری کتب میں جہاں وحی کی تشریح فرمائی ہے وہاں اپنے تجربہ کی بنیاد پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہایت سرعت کے ساتھ نازل ہوتا ہے.یہی حقیقت قرآن کریم نے بھی بیان کی ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں آتا ہے لَاتُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ.اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ (القیامۃ:۱۷،۱۸) چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الٰہی سرعت کے ساتھ نازل ہوتی تھی اس لئے آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے جاتے تھے تاکہ الفاظ پر قابو پاسکیں.اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تیرا الہام شرعی ہے اور شرعی الہام بھولا نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ بھولے
Page 45
تو وحی متلو ادھوری رہ جائے.اس آیت کے بے شک اور بھی معنے ہیں مگر ایک ظاہری معنے یہ بھی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی وحی چونکہ سرعت کے ساتھ نازل ہوتی تھی اس لئے آپ بھی جلدی جلدی اس کلام کو اپنی زبان سے دہرانے لگتے.پس قرآن کریم بھی اس حقیقت کو درست تسلیم کرتا ہے کہ وحی الٰہی جلدی جلدی نازل ہوتی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنے تجربہ کی بنیاد پر یہی تحریر فرمایا ہے کہ وحی الٰہی میں بہت بڑی شان اور عظمت اور سرعت پائی جاتی ہے.لغوی معنے بھی وحی کے اشارۃالسریعہ کے ہیں جو اس کیفیت پر روشنی ڈالتے ہیں جو نزول وحی کے وقت ہوتی ہے.پھر کہتے ہیں وَذَالِکَ یَکُوْنُ بِالْکَلَامِ عَلٰی سَبِیْلِ الرَّمْزِ وَالتَّعْرِیْضِ کبھی یہ اشارہ کلام کے ذریعہ ہوتا ہے لیکن اس میں کوئی تعریض یا رمزپائی جاتی ہے کھلا اور واضح کلام نہیںہوتا وَقَدْ یَکُوْنُ بِصَوْتٍ مُّـجَرَّدٍ عَنِ التَّـرْکِیْبِ اور کبھی صرف آوازاس میں پائی جاتی ہے اور الفاظ نہیں ہوتے وَبِاِشَارَۃِ بَعْضِ الْـجَوَارِحِ اور کبھی بعض جوارح کے اشاروں سے کام لیا جاتا ہے جیسے بعض لوگ آنکھ سے اشارہ کر تے ہیں بعض انگلی سے اشارہ کرتے ہیں بعض سر کو ہلا کر اشارہ کردیتے ہیں وَبِالْکِتَابَۃِ اور کبھی کتابت بھی اس میں شامل ہوتی ہے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ مفردات والے یہاں وحی الٰہی کا ذکر نہیں کررہے بلکہ وحی کے صرف لغوی معنے بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کیا ہیں.پھر لکھتے ہیں وَقَدْ حُـمِلَ عَلٰی ذَالِکَ قَوْلُہٗ تَعَالٰی عَنْ زَکَرِیَّا.انہی معنوں پر قرآن کریم کی اس آیت کو محمول کیا گیا ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتی ہے کہ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا یعنی قرآن کریم میں جویہ آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے گئے اور ان کی طرف وحی کی کہ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا تم صبح اور شام خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو تاکہ مجھ سے خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ جلد پورا ہو.چونکہ اس وقت حضرت زکریا کو خاموش رہنے کا حکم تھا اس لئے حضرت زکریا کی باتوں کا جو ذکر قرآن کریم میں آتا ہے اس کے متعلق علماء میں اختلاف ہے.چنانچہ قَدْ قِیْلَ رَمَزَ بعض لوگوں نے اس کے یہ معنے کئے ہیں کہ انہوں نے اشارہ سے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم صبح و شام خدا تعالیٰ کی تسبیح کرو تاکہ اس کا فضل نازل ہو.وَقِیْلَ اِعْتِبَارٌ اور بعض نے اس کے معنے اعتبار کے کئے ہیں.اعتبار کے معنے لغت میں کسی کے قول یا فعل سے استنباط کرنے اور عقلی طور پر ایک نتیجہ اخذ کرنے کے ہوتے ہیں.اس لحاظ سے معنے یہ ہوں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عملی حالت اور ان کے خشوع و خضوع اور تضرع اور زاری اور توجہ الی اللہ کو دیکھ کر قوم نے خودبخودیہ نتیجہ نکال لیا کہ ہمیں یہی حکم دے رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں
Page 46
مشغول ہوجائیں.وَقِیْلَ کَتَبَ اور بعض لوگوں نے یہ معنے کئے ہیں کہ انہوںنے لکھ کر اپنی قوم کو یہ نصیحت کی.جیسے مجمع البحار کے حوالہ میں یہ ذکر آچکا ہے کہ چونکہ انہوںنے نذر مانی ہوئی تھی کہ میں نے لوگوں سے بولنا نہیں اس لئے انہوں نے اپنے ہاتھ سے زمین پر یہ الفاظ لکھ دیئے کہ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّ عَشِيًّا.وَعَلٰی ھٰذِہِ الْوُجُوْہِ قَوْلُہٗ اور انہی وجوہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا.اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے کوئی نہ کوئی دشمن مقرر کیا ہے.چنانچہ انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان ہیں ان میں سے بعض بعض کی طرف ملمع سازی اور دھوکا و فریب کی باتیں وحی کرتے ہیں.وہ کہتے ہیں یہاں يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ کے یا تو یہ معنے ہیں کہ وہ رمز کرتے ہیں یا یہ معنے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو لکھتے ہیں اور یا پھر یہ معنے ہیں کہ وہ مختلف ذرائع سے اپنے مقصد و مدعا کو ان تک پہنچادیتے ہیں.وَقَولُہٗ وَ اِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ۠ فَذَالِکَ بِالْوَسْوَاسِ الْمُشَارِ اِلَیْہِ بِقَوْلِہٖ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وَبِقَوْلِہٖ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَاِنَّ لِلشَّیْطٰنِ لَمَّۃُ الشَّـرِّ اور یہ جو قرآن کریم میں آیت آتی ہے کہ اِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ۠ شیطان اپنے اولیاء کی طرف وحی کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈال کر ان کے دلوں کو خراب کرتے ہیں.اسی کی طرف اس آیت میںاشارہ پایا جاتا ہے کہ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخ یعنی خناس کے وساوس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے.اور خناس وہی ہوتا ہے جو مختلف قسم کے وساوس و شبہات کے ذریعہ خدا اور اس کے رسول کے خلاف دل میں باتیں پیدا کردے.وَبِقَوْلِہٖ عَلَیْہِ السَّلَامُ وَاِنَّ لِلشَّیْطٰنِ لَمَّۃُ الشَّـرِّ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں شیطانی وساوس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ اِنَّ لِلشَّیْطٰنِ لَمَّۃُ الشَّـرِّ شیطانی تحریکوں سے تمہیں ہر وقت اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ وہ نقصان کا موجب ہوتی ہیں.وَیُقَالُ لِلْکَلِمَۃِ الْاِلٰھِیَّۃِ الَّتِیْ تُلْقٰی اِلٰی اَنْبِیَاءِہٖ وَ اَوْلِیَاءِہٖ وَحْیٌ اور وہ کلمہ الٰہیہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء کی طرف نازل کیا جاتا ہے اسے بھی وحی کہتے ہیں.ان الفاظ میں مفردات والوں نے ایک بہت بڑے مسئلہ کا حل کردیاہے جو موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے لئے ٹھوکر کا موجب بنا ہوا ہے.میں نے دیکھا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق ہماری جماعت کی طرف سے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی تو مسلمان شور مچادیتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الٰہی کہاںنازل ہوسکتی ہے.حالانکہ مفردات والے لکھتے ہیں وَیُقَالُ لِلْکَلِمَۃِ الْاِلٰھِیَّۃِ الَّتِیْ تُلْقٰی اِلٰی اَنْبِیَاءِہٖ وَاَوْلِیَاءِہٖ وَحْیٌ.اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے اولیاء کی طرف جو کلام نازل ہوتا ہے اسے وحی کے نام سے موسوم کیا
Page 47
جاتا ہے.ہم تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی تسلیم کرتے اور آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں.اس لئے ضروری ہے کہ ہم آپ کے الہامات کو وحی قرار دیں.لیکن مفردات والوں نے تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو بھی جو ولی پر نازل ہوتا ہے وحی قرار دیا ہے اور درحقیقت یہی بات صحیح اور درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام بھی نازل ہو خواہ وہ نبی پر نازل ہو یا ولی پر بہرحال وحی ہوتاہے.اب تو اس قسم کی بحثیں کم ہوگئی ہیں لیکن جب میں بچہ تھا اس وقت مخالفین کی طرف سے بڑے بڑے اشتہارات اس مضمون کے شائع ہوا کرتے تھے کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ کافر اور بے دین ہیں کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے.لوگوں میں اس وقت مخالفت کا ایک عجیب طوفان بپا تھا اور وحی کے لفظ کے استعمال پر مخالفین کی طرف سے بڑے بڑے فتوے دیئے جاتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کافر اور بے دین قرار دیا جاتا تھا.مگر امام راغب اس جگہ کھلے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جوکلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اس کے ولیوں پر نازل ہوتاہے اس کلام کو بغیر کسی فرق اور امتیاز کے وحی کہا جاتا ہے.پھر فرماتے ہیں وَذَالِکَ اَضْـرُبٌ اور یہ کلام کئی اقسام کا ہوتا ہے.حَسْبَ مَا دَلَّ عَلَیْہِ قَوْلُہٗ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ١ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ(الشوریٰ:۵۲).اسی کی طرف قرآن کریم کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا یعنی کسی بندے کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے ان تین صورتوں کے کہ یا اس پر وحی نازل کرتا ہے یا اس سے مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ کلام کرتا ہے یا اس کی طرف رسول بھیجتا ہے.فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ اور وہ فرشتہ رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت اس انسان کی طرف وہ وحی نازل کرتا ہے جس کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کے منشاء میں داخل ہوتا ہے یا جس حد تک اللہ تعالیٰ کوئی کلام اتارنا چاہتا ہے اس حد تک اپنے رسول کے ذریعہ اتار دیتا ہے.اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند شان والا اور بڑی حکمت والا ہے.امام راغب لکھتے ہیں وَذَالِکَ اِمَّا بِرَسُوْلٍ مُّشَاھَدٍ.اس وحی کے وقت یا تو ایسا رسول سامنے آتا ہے کہ تُرٰی ذَاتُہٗ اس کی ذات نظر آتی ہے.وَیُسْمَعُ کَلَامُہٗ اور وہ جو کچھ بات کرتا ہے وہ سنی جاتی ہے.کَتَبْلِیْغِ جِبْـرِیْلَ عَلَیْہِ السَّلَامُ لِلنَّبِیِّ فِیْ صُوْرَۃٍ مُّعَیَّنَۃٍ.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل ایک خاص شکل میں ظاہر ہوکر خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کرتا تھا.حدیثوں میں آتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت غار حرا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور انہوں نے آپ سے کلام کیا.پھر فترۃ کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا مگر غار حرا
Page 48
میں نہیں بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے.اسی طرح بخاری اور بعض دوسری کتب احادیث میں ذکر آتا ہے کہ بعض دفعہ جبریل ظاہر ہوئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بالمشافہ باتیں کیں جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے ہم کلام ہوتا ہے.غرض جبریل کسی نہ کسی صورت میں متشکل ہوکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے.اسی لئے مفردات والوں نے یہ نہیں کہا کہ فِی الصُّوْرَۃِ الْمُعَیَّنَۃِ اپنی معین صورت میں جبریل ظاہر ہوتا ہے بلکہ فِیْ صُوْرَۃٍ مُّعَیَّنَۃٍ کہا ہے یعنی کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے.یہ امتیاز انہوں نے اس لئے کیا ہے کہ درحقیقت جبریل کی کوئی ایک شکل نہیں.حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے.جب حرا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا تو ایک شَابٌّ کی شکل میں ظاہر ہوا.جب فترۃ وحی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تو وہ اتنی مہیب شکل میں ظاہر ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر گھبراگئے تھے.وہ شکل اس قدر وسیع طور پر پھیلی ہوئی تھی کہ سارے آسمان پر محیط تھی.لیکن مدینہ منورہ میں جب جبریل ظاہر ہوا تو اس کی شکل آپ کے ایک خوبصورت صحابی دحیہ کلبی سے ملتی تھی.( بخاری کتاب فضائل القرآن باب کیف نزل الوحی وَاَوَّلُ مَا نَزَلَ ) غرض مختلف اوقات میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں جبریل کا ظاہر ہونا صاف بتاتا ہے کہ جبریل کی کوئی ایک شکل نہیں.جبریل تو ایک فرشتہ ہے اور اس لحاظ سے وہ ویسا ہی ہے جیسے اور فرشتے ہیں مگر جب وہ کسی بندے پر ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق ایک مثالی شکل اختیار کرلیتا ہے.جبریل کے صورت معینہ میں آنے کی وجہ جب جبریل ایک خوبصورت شَابٌّ کی شکل میں آپ پر ظاہر ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استمالت قلب کو مدّ ِنظر رکھ کر ایسا کیا کیونکہ اس وقت وحی کے نزول کا ابتدا تھا اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلائے کہ ڈر اور فکر کی بات نہیں.اس نے اپنے قرب کے لئے آپ کو مخصوص کرلیا ہے اور وہ آئندہ اپنے بہت بڑے فضلوں کا آپ کو مورد بنانے والا ہے.پس چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور آپ سے اپنی محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے مدّ ِنظر تھا اس لئے اس نے جبریل کو ایک نوجوان کی شکل میں آپ پر ظاہر فرمایا.اس کے بعد جب جبریل ایک نہایت ہی مہیب اور خوفناک شکل میں آپ کودکھائے گئے تو اس میں حکمت یہ تھی کہ ابتدائے وحی پر چھ ماہ کا عرصہ گذرچکا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا کلام اہل مکہ تک پہنچانا شروع کردیا تھا گو زیادہ زور کے ساتھ تبلیغ بعدمیں شروع کی گئی ہے مگر انفرادی رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام
Page 49
لوگوں کو سنانا شروع کردیا تھا اور اہل مکہ میں مخالفت اور تکذیب کے آثار شروع ہوگئے تھے.اسی وجہ سے جبریل آپ کو ایک سخت مہیب شکل میں دکھائے گئے تا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہو کہ اب انذار کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے.وہ مہیب شکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں تھی بلکہ اس آنے والی وحی کے پیش خیمہ کے طور پر تھی جس میں مخالفین کی تباہی اور بربادی کی خبریں دی جانے والی تھیں.اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی کی صورت میں جبریل کو دیکھا تو اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر کسی اجنبی کی شکل آپ کو دکھائی جاتی تو صحابہؓ کے دل میں شبہ گذرتا کہ ممکن ہے یہ کوئی اور شخص ہو جسے ہم نہ جانتے ہوں باہر سے آیا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرکے چلا گیا ہو.مگر دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل کے آنے پر ان کے دلوں میں اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ دحیہ کلبی ان کا ہمسایہ تھا اور اگر ان کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا کہ یہ شکل جو ہم نے دیکھی ہے دحیہ کلبی کی تھی یا جبریل کی تو وہ فوراً دحیہ کلبی سے پوچھ سکتے تھے کہ میاں تم کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تھے یا نہیں اور جب وہ کہتا کہ میں تونہیں آیا تھا تو انہیں یقین آجاتا کہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتھا وہی درست تھا اور درحقیقت جبریل ہی دحیہ کلبی کی شکل میں آپ کے پاس آیا تھا.پس صحابہؓ کو اس بات کا یقین دلانے کے لئے کہ جبریل ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرہا ہے اللہ تعالیٰ اسے دحیہ کلبی کی شکل میںنازل فرماتا تاکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو یہ بتائیں کہ ذَالِکَ جِبْـرِیْلُ.یہ جبریل تھا جو ابھی تمہارے سامنے میرے ساتھ باتیں کرتا رہا تو ان کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو کہ یہ تو دحیہ کلبی تھا.وہ فوراً سمجھ جاتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمارہے ہیں درست ہے.کیونکہ دحیہ کلبی تو اس وقت فلاں جگہ موجود ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں دو مختلف مقامات پر اپنے جسم کے ساتھ دیکھا جاسکے.مثلاً بشارت الرحمٰن صاحب ہمارے کالج کے پروفیسر ہیں.بشارت کے معنے خوشخبری کے ہیں اور رحمٰن اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان پر بار بار رحم کرنے والی ہے.اگر وہ کسی شخص کو چلتے چلتے عین بیداری کی حالت میں نظر آجائیں اور اس کا قلب محسوس کرے کہ یہ درحقیقت ایک کشفی نظارہ ہے جو مجھے دکھایا گیا ہے تو اس کے بعد اپنے مزید اطمینان اور تسلی کے لئے اگر وہ بشارت الرحمٰن صاحب کا واقف ہے تو ان سے دریافت کرے گا کہ کیا کل ڈاکخانہ کے پاس یا فلاں جگہ فلاں وقت آپ ہی مجھے ملے تھے؟ وہ کہیں گے کہ میں تو آپ سے نہیں ملا.میں تو اس وقت ڈاکخانہ میں گیا ہی نہیں اپنے گھر میں بیٹھا تھا.اس بات سے اسے یقین آجائے گاکہ وہ جو میرے دل میں یہ احساس تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشفی رنگ میں ایک نظارہ دکھایا گیا ہے بالکل درست ہے.اگر
Page 50
جسمانی نظارہ ہوتا تو انہیں بھی پتہ ہوتا کہ میںفلاں دن اور فلاںوقت اپنے دوست سے ملا تھا.اسی طرح اگر جبریل دحیہ کلبی کی شکل میں نہ آتے بلکہ کسی اور اجنبی انسان کی شکل اختیار کرکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آجاتے، آپ سے مصافحہ بھی کرتے، باتیں بھی کرتے اور پھر چلے جاتے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جبریل تھا جو مجھ سے باتیں کرتا رہا تو صحابہؓ کے دلوںمیںیہ خیال گذرسکتا تھا کہ ہم یہ کس طرح مان لیں.ممکن ہے کوئی اجنبی آدمی ہو اور اسے جبریل کہہ دیا گیا ہو.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان رکھتے تھے اور آپ جو کچھ بھی فرماتے وہ شرح صدر کے ساتھ اس کی تصدیق کرنے کے لئے تیار رہتے تھے.مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایک یقین وہ ہوتا ہے جو تمام مادی ثبوتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک یقین وہ ہوتا ہے جو سابق یقین کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے.اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجنبی انسان کے متعلق بھی فرما دیتے کہ ذَالِکَ جِبْـرِیْلُ.وہ جبریل تھا جو میرے پاس آیا تو چونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین رکھتے تھے وہ اسے بھی مان لیتے مگر دحیہ کلبی کی صورت میںجبریل کا آنا اور پھر صحابہؓ کا خود دحیہ کلبی سے پوچھ کر تسلی کرسکنا کہ بتائو تم تو کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آئے تھے اور اس کا انکار کرنا ایک ایسا یقین تھا جو صرف سابق ایمان کی وجہ سے ان کو حاصل نہیں ہوسکتا تھا بلکہ یہ ایک زائد ثبوت تھا اس بات کا کہ ان کے حواس بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل درست ہے.گویا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کرسکتے تھے اس وجہ سے بھی کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں اس لئے ٹھیک ہے اور اس وجہ سے بھی کہ چونکہ ہمارے اپنے حواس بھی اس کی سچائی کی شہادت دیتے ہیں اس لئے یہ ٹھیک ہے اور اس وجہ سے بھی کہ چونکہ دحیہ کلبی بھی تصدیق کرتا ہے اس لئے یہ ٹھیک ہے.غرض تینوں مقامات پر تین الگ الگ مقاصد کے ماتحت جبریل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا.بعض لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کیا اس کی زبان ہے جس سے وہ بولتا ہے.ہم کہتے ہیں اس کی زبان تو نہیں مگر اس میں قدرت موجود ہے اور وہ اپنی قدرت سے بغیر زبان کے کلام پیدا کردیتا ہے.یہی حال جبریل کا ہے وہ ملک ہے مگر ہر موقع کے مناسب حال مختلف شکلیں بدل لیتا ہے.کبھی ماں کی شکل اختیارکرلیتا ہے، کبھی بیٹی کی شکل اختیار کرلیتا ہے، کبھی بیٹے کی شکل اختیار کرلیتا ہے، کبھی بیوی کی شکل اختیار کرلیتا ہے، کبھی مرد کی شکل اختیار کرلیتا ہے، کبھی انسانی شکل کے علاوہ کبوتر یا کسی اور جانور کی شکل اختیار کرلیتا ہے.اور شکلوں کے اس اختلاف سے یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہورہا ہے
Page 51
اس کی کیا شان ہے یا تمہارے دوستوں کے لئے اس کی کیا شان ہے یا تمہارے دشمنوں کے لئے اس کی کیا شان ہے.گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو صورتوں میں الہام نازل ہوتا ہے.ایک الہام ان فقرات کی صورت میں نازل ہوتا ہے جو جبریل کی زبان سے بندہ سنتا ہے اور ایک الہام خود جبریل کی شکل میں ہوتا ہے.اگر وہ ایک مہیب اور خوفناک شکل میں آسمان اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا تو اس کے معنے یہ تھے کہ وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اب ساری زمین پر قضاء جاری کرنے والا ہے.ساری دنیا کی قضاء اب اس کلام کے ساتھ وابستہ ہے.وہی عمل خدا تعالیٰ کے حضور مقبول ہوگا جو اس کلام کے مطابق ہوگا.اور وہ عمل جو اس کلام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسان بجالائے گا اسے ردّ کردیا جائے گا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استمالت قلب مراد تھی اس وقت جبریل آپ کو غار حرا میں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں نظر آیا اور جب صحابہؓ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جبریل ہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو تو اس وقت جبریل ایک صحابی کی شکل میں نظر آیا تاکہ وہ خود بھی پتہ لگاسکیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص باتیں کررہا تھا وہ دحیہ کلبی نہیں بلکہ جبریل ہی ہے.غرض جبریل ہمیشہ فِیْ صُوْرَۃٍ مُّعَیَّنَۃٍ نازل ہوتا ہے نہ کہ فِی الصُّوْرَۃِ الْمُعَیَّنَۃِ اپنی ذاتی شکل و صورت میں.پھر کہتے ہیں وَاِمَّا بِسَمَاعِ کَلَامٍ مِّنْ غَیْـرِ مُعَایَنَۃٍ کَسَمَاعِ مُوْسٰی کَلَامَ اللہِ کبھی ایساہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام تو نازل ہوتا ہے مگر جبریل اس کے ساتھ نہیں آتا.کان میں آواز آتی ہے انسان اس آواز کو سنتا اور سمجھتا ہے مگر کوئی چیز نظر نہیں آتی.جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا.وَاِمَّا بِاِلْقَاءٍ فِی الرَّوْعِ کَمَا ذَکَرَ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِیْ رَوْعِیْ اور کبھی کوئی بات بطور القاء دل میں ڈال دی جاتی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ روح القدس نے ایک بات میرے دل میں ڈالی ہے کوئی معین الفاظ نہیں تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہوں.ورنہ آپ ان کا بھی ذکر فرماتے یا کہتے کہ جبریل نے مجھے آکر یوں کہا ہے.آپ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی صرف اتنا فرمایا ہے کہ اَنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِیْ رَوْعِیْ روح القدس نے میرے قلب میں فلاں بات ڈالی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے (مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ دل کے خیال کو الہام کہہ دیا جائے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان پر ساتھ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جبریل یا کوئی دوسرا فرشتہ یا خدا تعالیٰ بذات خود باہر سے یہ بات میرے دل میں ڈال رہا ہے اور خود میرے دل سے یہ خیال پیدا نہیں ہورہا).
Page 52
وَاِمَّا بِاِلْھَامٍ نَـحْوَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِاور یا کبھی کلام الٰہیہ کا نزول الہام کے ذریعہ سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے اُمّ موسیٰ کی طرف وحی کی.وَ اِمَّا بِتَسْخِیْـرٍ نَـحْوَ قَوْلِہٖ وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اور کبھی وحی تسخیر ہوتی ہے یعنی طبعی طور پر کسی چیز کی فطرت میں ایک بات پیدا کردی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی.اس جگہ وحی سے مرادوحی لفظی نہیں بلکہ وحیٔ تسخیر ہے.وحیٔ تسخیر سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عربی، اردو یا انگریزی زبان میں کوئی کلام نازل ہوتا ہے.یہ بھی مراد نہیں کہ تمثیلی زبان میں کوئی نظارہ دکھایا جاتا ہے اور یہ بھی مراد نہیں کہ جبریل بھیجا جاتا ہے.بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کام بعض چیزوں کی فطرت میں داخل کردیتا ہے اور وہ مجبور ہوتی ہیں کہ اسی رنگ میں کام کریں جس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کردیا ہے.جیسے سورج مسخر ہے، ایک مقرر منزل کی طرف چلنے پر اور زمین مسخر ہے سورج کے گرد گھومنے پر.اسی طرح کوئی پودا پھول پیدا کرنے پر مسخر ہے.کوئی پھل پیدا کرنے پر مسخر ہے کوئی کسی اور کام پر مسخر ہے گویا فطرت میں جو بات ودیعت کردی جائے اسے وحیٔ تسخیر کہتے ہیں.اسی قسم کی وحی مکھی کو ہوئی ہے اَوْ بِـمَنَامٍ یا رئویا اور خواب کی حالت میں کوئی نقشہ انسان کو نظر آجاتا ہے کَمَا قَالَ عَلَیْہِ السَّلَامُ انْقَطَعَ الْوَحْیُ وَبَقِیَتِ الْمُبَشِّـرَاتُ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی منقطع ہوگئی اور مبشرات باقی رہ گئے ہیں اور مبشرات سے مراد کیا ہے رُؤْیَا الْمُؤْمِنِ.مومن جو سچے رؤیا دیکھتا ہے ان کو مبشرات کہا جاتا ہے.فَالْاِلْھَامُ وَالتَّسْخِیْـرُ وَالْمَنَامُ دَلَّ عَلَیْہِ قَوْلُہٗ اِلَّا وَحْیًا.پس الہام تسخیر اور منام پر قرآن کریم کی آیت میں اِلَّا وَحْیًا کے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ دلالت کرتے ہیں وَسَـمَاعُ الْکَلَامِ غَیْـرَ مُعَائِنَۃٍ دَلَّ عَلَیْہِ قَوْلُہٗ اَوْمِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ.اور وہ کلام جس کی کانوں میں تو آواز آتی ہے مگر کوئی شکل نظر نہیں آتی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتاہے کہ اَوَْمِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ.وَتَبْلِیْغُ جِبْـرِیْلَ فِیْ صُوْرَۃٍ مُّعَیَّنَۃٍ دَلَّ عَلَیْہِ قَوْلُ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ.اور وحی کی یہ صورت کہ بعض دفعہ جبریل اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے اس پر یہ آیت شاہد ہے کہ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا یعنی اللہ تعالیٰ اس رنگ میں بھی وحی نازل کرتا ہے کہ بعض دفعہ اپنے کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو واسطہ بن کر اس کا پیغام بندے کو پہنچاتا ہے.وحی الٰہی کے متعلق مفردات والوں کی مذکورہ بالا تشریح کے متعلق میں یہ امر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس میں بعض غلطیاں ہیں جو زمانہ نبوت سے بُعد کی وجہ سے ان سے ظاہر ہوئی ہیں اور جن کا اس بحث کے ضمن میں مدّ ِنظر رکھنا نہایت ضروری ہے.وحی کے معنے کرنے میں امام راغب کی تین غلطیاں سب سے پہلی اور بڑی غلطی تو یہ ہے کہ
Page 53
وحی الٰہی کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے دو مختلف مضامین کو مخلوط کردیا ہے.وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نازل ہوتا ہے اس کی کیا قسمیں ہیں.مگر اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس وحی کو بھی بیان کردیا ہے جو مکھی کی طرف ہوئی.حالانکہ یہ بالکل واضح بات تھی کہ وہ یہ بحث نہیں کررہے تھے کہ لغت کے لحاظ سے وحی کے کیا معنے ہیں یا وحی کا اطلاق کن کن معانی پر ہوسکتا ہے.بلکہ وہ بتانے یہ لگے تھے کہ بشر پر جو وحی الٰہی نازل ہوتی ہے اس کی کیا قسمیں ہیں.مگر ان کا ذکر کرتے ہوئے اس وحی کا بھی انہوں نے ذکر کردیا جو مکھی کی طرف ہوئی.چنانچہ انہوں نے بحث یہ اٹھائی تھی کہ وَیُقَالُ لِلْکَلِمَۃِ الْاِلٰھِیَّۃِ الَّتِیْ تُلْقٰی اِلٰی اَنْبِیَاءِہٖ وَ اَوْلِیَاءِہٖ وَحْیٌ کہ ان کلماتِ الٰہیہ کو بھی وحی کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اس کے اولیاء کی طرف نازل ہوتے ہیں وَذَالِکَ اَضْـرُبٌ اور اس کی کئی قسمیں ہیں.حَسْبَ مَا دَلَّ عَلَیْہِ قَوْلُہٗ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اِلٰی قَوْلِہٖ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ جیسا کہ خدا تعالیٰ کا یہ قول اس پر دلالت کرتا ہے کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا مگر اس رنگ میں کہ اس پر براہِ راست وحی نازل کرتا ہے یا اس سے وراء حجاب گفتگو کرتا ہے یا اس کی طرف کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا ہے.اب ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس وحی کا ذکر رہاہے جو بشر پر نازل ہوتی ہے مگر اس کی تشریح کرتے ہوئے مفردات والے لکھتے ہیں وَاِمَّا بِتَسْخِیْـرٍ نَـحْوَ قَوْلِہٖ وَاَوْحٰی رَبُّکَ اِلَی النَّحْلِ یا وحیٔ تسخیر ہوتی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی.جب اس جگہ اس وحی کا ذکر ہورہا تھا جو بشر پر ہوتی ہے تو غیربشر کی وحی کا اس تشریح میں ذکر ہی کس طرح آسکتا تھا.پس پہلی غلطی تو یہ ہے کہ آیت اور لغت کو انہوں نے مخلوط کردیا ہے.بے شک لغت کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے کہ وحی کی ایک قسم وحیٔ تسخیر بھی ہے جیسا کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی ہوئی مگر مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا میں بشر کا ذکر ہے غیر بشر کا نہیں.مگر تشریح کرتے ہوئے وہ مکھی کا ذکر بھی لے آئے اور ان کے ذہن پر آیت قرآنی کی تشریح کی بجائے لغت غالب آگئی.انہیں یہ خیال نہ رہا کہ یہاں اس وحی کا ذکر ہے جو بشر کی طرف ہوتی ہے.اس وحی کا ذکر ہی نہیں جو غیر بشر کی طرف ہو.اس لئے وحی تسخیر کا اس دوران میں کوئی ذکر ہی نہیں آسکتا تھا.دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ذَالِکَ اِمَّا بِرَسُوْلٍ مُّشَاھَدٍ تُرٰی ذَاتُہٗ یا تو یہ کلام کسی رسول کے ذریعہ آتا ہے جس کی شکل سامنے نظر آتی ہے وَیُسْمَعُ کَلَامُہٗ اور اس کی آواز بھی سنی جاتی ہے وَاِمَّا بِسَمَاعِ کَلَامٍ مِنْ غَیْـرِ مُعَائِنَۃٍ یا بغیر کسی چیز کے دکھائی دینے کے محض آواز آجاتی ہے.کَسِمَاعِ مُوْسٰی کَلَامَ اللہِ جیسے موسٰی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا.وَ اِمَّا بِاِلْقَاءٍ فِی الرَّوْعِ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات
Page 54
دل میں ڈال دی جاتی ہے مگر اس کے بعد کہتے ہیں وَاِمَّا بِاِلْھَامٍ نَـحْوَ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ یا یہ کلام الہام کے ذریعہ نازل ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے اُمّ موسٰی کی طرف وحی کی.جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک وہ قسم بھی آچکی جس میں جبریل کا نزول ہوتا ہے، وہ قسم بھی آچکی ہے جس میں آواز سنائی دیتی ہے، وہ قسم بھی آچکی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات دل میں ڈال دی جاتی ہے تو پھر الہام کون سا باقی رہا جس کا وہ علیحدہ ذکر کررہے ہیں اور جس کی مثال میں انہوں نے اُمّ موسیٰ کا واقعہ پیش کیا ہے.یہ صاف بات ہے کہ جبریل کے ذریعہ جو کلام آتا ہے وہ بھی الہام ہوتا ہے.اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آواز آتی ہے تو وہ بھی الہام ہوتا ہے اور یہی الہام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا مگر انہوں نے اِمَّا کہہ کر ایک اور شق قائم کردی ہے کہ وحی کی ایک قسم الہام بھی ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا کہ اَنْ اَرْضِعِيْهِ حالانکہ یہ بات ان کی پہلی بیان کردہ قسموں میں ہی شامل ہے کوئی علیحدہ بات نہیں جسے زائد طور پر اِمَّا کہہ کر بیان کرنے کی ضرورت ہوتی.اس موقعہ پر یا تو انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ وحی اور چیز ہوتی ہے اور الہام اور چیز.اس لئے میں الہام کا علیحدہ ذکر کررہا ہوں اور الہام اور وحی میں یہ فرق ہوتا ہے مگر انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا اور بلاوجہ ایک علیحدہ شق اِمَّا کہہ کر قائم کردی حالانکہ یہ پہلے مضمون سے کوئی مغائر مضمون نہیں ہے.اگر کہا جائے کہ الہام کے معنے ان کے نزدیک ’’در دل انداختن‘‘ کے ہوتے ہیں یعنی وہ بات جو دل میں ڈال دی جائے اسے الہام کہتے ہیں اور جو کلام الفاظ کی شکل میں نازل ہو اسے وحی کہتے ہیں.اسی لئے انہوںنے الہام کا علیحدہ ذکر کیاہے تو یہ بات بھی غلط ہے.کیونکہ وہ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ وَاِمَّا بِاِلْقَاءٍ فِی الرَّوْعِ کَمَا ذَکَرَ عَلَیْہِ السَّلَامُ اَنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِیْ رَوْعِیْ کہ وحی بعض دفعہ القاء فی الروع کی صورت میں بھی ہوتی ہے.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے فلاں بات میرے دل میں ڈال دی ہے.جب اِلْقَاء فِی الرَّوْعِ کا پہلے ذکر آچکا ہے تو اس کے بعد اِمَّا بِاِلْھَامٍ نَـحْوَ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ کہنا بتاتا ہے کہ ان کا یہ منشا نہیں ہوسکتا کہ الہام سے مراد در دل انداختن ہے کیونکہ یہ مضمون پہلے آچکا ہے.میرے نزدیک تو انہوں نے بھول کر دوبارہ اِمَّا بِاِلْھَامٍ نَـحْوَ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى اَنْ اَرْضِعِيْهِ لکھ دیا ہے.چنانچہ مجمع البحار والوں نے کہا ہے کہ مفردات راغب کی یہ بات غلط ہے.چنانچہ وہ لکھتے ہیں وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰۤى اُمِّ مُوْسٰۤى وَحْیُ اِعْلَامٍ لَا اِلْہَامٍ لِقَوْلِہٖ تَعَالٰی اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ وحی جو نازل ہوئی تھی کہ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ ہم اسے الہام نہیں کہہ سکتے کیونکہ الہام تو در دل انداختن کو کہتے ہیں اور
Page 55
یہاں صاف الفاظ موجود ہیں کہ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ ہم اسے تیری طرف واپس لوٹائیں گے.یہ تو ہوسکتا ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دی جائے مگر اس کے الفاظ معین صورت میں نہیں آتے.الفاظ کا معین صورت میں نازل ہونا بتارہا ہے کہ الہام نہیں اعلام ہے.اعلام کے معنے اظہار کے ہوتے ہیں اور الہام سابق مفسرین کے نزدیک در دل انداختن کو کہا جاتا ہے.یہ بھی عربی زبان کا ایک کمال ہے کہ حروف کے معمولی فرق کے ساتھ معانی میں تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے.اگر ایک آدمی سے کوئی بات کہی جائے تو اسے اعلام کہتے ہیں.لیکن اگر کئی آدمیوں سے بات کہی جائے تو اسے اعلان کہتے ہیں.چونکہ میم پہلے آتا ہے اور نون بعد میںاس لئے ایک آدمی سے تعلق رکھنے والی بات کو اعلام کہا جاتا ہے اور زیادہ آدمیوں سے تعلق رکھنے والی بات کو اعلان کہا جاتا ہے.بہرحال مجمع البحار والوں نے ان الفاظ میں مفردات کی ہی تردید کی ہے کہ اس میں جو لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا یہ صحیح نہیں.انہیں وحی اعلام ہوئی تھی کیونکہ اس کے معین الفاظ تھے وہ الہام نہ تھی کیونکہ الہام تو در دل انداختن کو کہا جاتا ہے.میرے نزدیک مفردات والوں نے بھول کر الہام کا دوبارہ ذکر کردیا ہے.کیونکہ قلبی الہام کا وہ اس سے پہلے خود ذکر کرچکے ہیں یا ممکن ہے ان کا مفہوم کچھ اور ہو، مبہم عبارت کی وجہ سے اس کا مطلب صحیح سمجھ میں نہ آتا ہو.الغرض وحی کے معنے کرتے ہوئے امام راغب صاحب نے جو یہ تشریح کی ہے کہ فَالْاِلْھَامُ وَالتَّسْخِیْـرُ وَالْمَنَامُ دَلَّ عَلَیْہِ قَوْلُہٗ اِلَّا وَحْیًا کہ الہام (جس کے معنے سابق علماء کے نزدیک در دل انداختن کے ہیں) اور تسخیر اور منام یہ وحی کے ماتحت آتے ہیں اور وراء حجاب سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے کہ خدا تعالیٰ خود کلام کرے لیکن نظر نہ آئے اور یُرْسِلَ رَسُوْلًا کا مطلب یہ لیا ہے کہ خدا تعالیٰ خود کلام نہ کرے بلکہ جبریل کے واسطہ سے اپنا کلام بھجوائے اور جبریل نظر نہ آئے.میرے نزدیک ان کی یہ تشریح درست نہیں کیونکہ نہ ہر وحی قرآنی کے وقت جبریل نظر آتے تھے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا کلام من وراء حجاب تھا.پھر ان کا من وراء حجاب سے یہ مراد لینا کہ خدا تعالیٰ نظر نہ آئے تو یہ تعریف تو ہر وحی پر چسپاں ہوگی خواہ کسی قسم کی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الوراء ہے.پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو منام کا نام وحی رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی نقل کرتے ہیں کہ اِنْقَطَعَ الْوَحْیُ وَبَقِیَتِ الْمُبَشِّـرَاتُ وحی منقطع ہوگئی ہے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں اور مبشرات سے مراد وہ سچے رؤیا ہیں جو مومنوں کو ہوتے ہیں.اگر منام کا نام ہی وحی ہے تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ اِنْقَطَعَ کَلَامُ وَرَاءِ الْـحِجَابِ اِلَّا الْوَحْیُ.اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو پس پردہ ہوا کرتا تھا وہ اب بند ہوچکا ہے اب صرف وحی باقی رہ گئی ہے جس سے مراد خوابیں ہیں.پس یہ تشریح جو مفردات والوں نے کی ہے اس قابل
Page 56
نہیں کہ اسے قبول کیاجائے.الہام کے معنے سمجھنے میں پہلے علماء کی غلط فہمی اصل بات یہ ہے کہ الہام کے معنے سمجھنے میں پہلے علماء کو بہت کچھ غلط فہمی ہوئی ہے اور اسی بنا پر وہ الہام کی تعریف یہ کرتے رہے ہیں کہ در دل انداختن.ایسی بات جو دل میں ڈال دی جائے اس کو الہام کہتے ہیں.حالانکہ الہام اور وحی دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ان میں کسی قسم کا فرق نہیں.یہ صرف صوفیاء کی اصطلاح تھی کہ انہوں نے اس کلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل ہوتا تھا الہام کہنا شروع کردیا تاکہ لوگ کسی فتنہ میں نہ پڑیں ورنہ الہام اور وحی میں کوئی فرق نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی کئی جگہ الہام کا لفظ استعمال کیا ہے مگر ساتھ ہی کہا ہے کہ میں اس کلام کو الہام صرف اس لئے کہتا ہوں کہ صوفیاء نے ایک اصطلاح قائم کردی ہے اور لوگوں میں اس اصطلاح کا رواج ہوگیا ہے.ورنہ میں اس بات کا قائل نہیں کہ الہام اور چیز ہے اور وحی اور چیز.جس چیز کا نام لوگ الہام رکھتے ہیں اسی چیز کا نام وحی ہے.پس الہام و ہ اصطلاح ہے جو لفظی کلام کے متعلق صوفیاء نے قائم کی ہے ورنہ قرآن کریم میں ہر جگہ وحی کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے الہام کا لفظ صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے اور وہ بھی وحی کے معنوں میں نہیں بلکہ میلانِ طبیعت کے معنوں میں جیسا کہ فرماتا ہے فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَ تَقْوٰىهَا(الشمس:۹) اللہ تعالیٰ نے انسان کو برائیوں اور نیکیوں کے متعلق الہام کیا ہے.اب اس کے معنے کسی خارجی الہام کے نہیں بلکہ صرف میلانِ طبع کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ تسخیر اور میلان میں فرق ہوتا ہے.میلان تو اختیاری ہوتا ہے لیکن تسخیر اختیاری نہیں ہوتی بلکہ جس لائن پر کسی چیز کو کھڑا کردیا جائے وہ مجبور ہوتی ہے کہ اسی لائن پر کھڑی رہے اور اس سے ذرا بھی اِدھر اُدھر نہ ہو.مثلاً مکھی یہ نہیں کرسکتی کہ وہ شہد بنانا چھوڑ دے لیکن انسان کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو تقویٰ اختیار کرے اور چاہے تو فجور کے راستہ پر چل پڑے.پس الہام کا لفظ جو مفردات والوں نے استعمال کیا ہے قرآن کریم میں ان معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوا جن معنوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے اور نہ الہام کا لفظ آیت میں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جو صوفیاء مراد لیتے ہیں.یہ لفظ بعد کے زمانہ میں صوفیاء نے لفظی وحی کے لئے ایجاد کیا ہے.لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے متعلق یہ وضاحت فرما دی ہے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے وہی وحی ہے مگر چونکہ لوگوں میں اس کے متعلق الہام کا لفظ رائج ہے اس لئے میں بھی اسے الہام کہہ دیتا ہوں ورنہ الہام اور وحی دونوں مترادف الفاظ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں.(براہین احمدیہ ، روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۲۴۴) الہامات کے ساتھ نزول ملائکہ کی وجہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جو یہ مسئلہ پایا جاتا ہے
Page 57
کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنا کلام ملائکہ کے ذریعہ نازل فرماتا ہے اس کے یہ معنے نہیں کہ ملائکہ صرف اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا والی وحی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں بلا واسطہ وحی کے ساتھ نازل نہیں ہوتے.حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے ہر الہام کے ساتھ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور کوئی ایک الہام بھی ایسا نہیں ہوسکتا جس کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ اس کے ساتھ فرشتے نازل نہیں ہوتے.مگر بعض لوگ غلط فہمی سے اس کا یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ جبریل ہر الہام کے ساتھ آکر کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں بات آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں.ملائکہ کے نزول کے صرف اتنے معنے ہیں کہ ہر الہام فرشتوں کی حفاظت کے ساتھ آتا ہے.یہ معنے نہیں کہ ہر الہام کے ساتھ فرشتے آکر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں فلاں بات پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات اس کی تائید میں موجود ہیں.مثلاً ایک الہام میں تو یہ ذکر آگیا کہ جَاءَنِیْ اٰیِلٌ (تذکرہ صفحہ ۵۵۹).میرے پاس جبریل آیا.مگر باقی الہامات کے ساتھ یہ بات بیان نہیں ہوئی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس رنگ میں نہیں جس رنگ میں لوگ سمجھتے ہیں.یہ نہیں کہ جب آپ کو یہ الہام ہوا تھا کہ اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ بَغْتَۃً (تذکرہ صفحہ ۳۳۳) تو فرشتوں نے آکر یہ کہا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ الہام نازل کرنے کا حکم دیا ہے.ایسا نہیں ہوا کرتا بلکہ بندہ اس وقت یہ محسوس کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ایک کلام مجھ پر نازل ہورہا ہے مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کلام کے ساتھ حفاظت کے لئے ضرور آتے ہیں.عام لوگوں کے الہامات کے ساتھ اس لئے نہیں آتے کہ اگر ان الہامات میں کوئی گڑ بڑ بھی ہوجائے تو پروا نہیں ہوتی لیکن انبیاء یا ان سے اتر کر وہ لوگ جو دنیا کی اصلاح کے لئے کھڑے کئے جاتے ہیںان کے الہامات چونکہ لوگوں کے لئے حجت ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی حفاظت میں اتارے جائیں.بہرحال الہامات کے ساتھ فرشتوں کا نازل ہونا یہ معنے نہیں رکھتا کہ مثلاً جب آیت الٓمّٓ.ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ١ۛۖۚ فِيْهِ اتری تھی تو اس وقت جبریل نے آکر یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ آیت آپ تک پہنچادوں.ایسا ذکر صرف چند سورتوں کے متعلق آیا ہے.مثلاً سورۃ البینہ کے متعلق آتا ہے یا یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام میں جبریل آتے اور جس قدر حصۂ قرآن نازل ہوچکا ہوتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس کا تکرار کیا کرتے.(مسند احمد بن حنبل مسند عبد اللہ بن عباس.بخاری کتاب بدء الوحی کیف کان بدء الوحی) مگر ہر الہام کے متعلق نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے کہ جبریل آکر یہ کہتا ہو کہ مجھے خدا نے فلاں بات پہنچانے کا حکم دیا ہے.ہاں ہر الہام کے ساتھ حفاظت جبریل ضرور ہوتی ہے.
Page 58
اصل بات یہ ہے کہ الہام کے وقت چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک آواز پیدا کرتا ہے اور اس آواز میں شیطان بھی دخل دے سکتا ہے اس لئے فرشتوں کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ بندہ کے دل میں وہ اس وحی کی صداقت کے متعلق یقین پیدا کریں جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ خواہ مجھے صلیب پر لٹکادیا جائے مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہوسکتاکہ وہ کلام جو مجھ پر نازل ہوتا ہے اسی خدا کا کلام ہے جس نے آدمؑ سے کلام کیا، جس نے نوحؑ سے کلام کیا، جس نے ابراہیمؑ سے کلام کیا، جس نے موسٰی سے کلام کیا، جس نے عیسٰیؑ سے کلام کیا اور جس نے سب سے بڑھ کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا.یہ یقین فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے ہی پید اہوتا ہے مگر عام لوگوں کے الہامات کے ساتھ چونکہ فرشتے نہیں اترتے اس لئے باوجود الہام کے ان کے اندر یقین اور ثبات اور استقلال نہیں پایا جاتا.ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا نے بتایا ہے کہ آپ سچے ہیں.اس وقت وہ روتے بھی ہیں گڑگڑاتے بھی ہیں اپنے سابق اعمال پر پشیمانی او رندامت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور آئندہ کے متعلق بڑے بڑے وعدے بھی کرتےہیں مگر چند دنوں کے بعد ہی مرتد ہوجاتے ہیں.اب جہاں تک ان کی بات کا تعلق ہوتا ہے وہ سچی ہوتی ہےواقعہ میں انہیں الہام ہوا ہوتا ہے اور اسی کی بناء پر وہ بیعت کے لئے آتے ہیں مگر چونکہ فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے ان کے قلب کو وہ ثبات نہیں بخشا جاتا جو انبیاء و اولیاء کے قلوب کو بخشا جاتا ہے اسی لئے وہ تھوڑے سے ابتلاء کو بھی برداشت نہیں کرسکتے اور ٹھوکر کھاجاتے ہیں.لیکن نبی کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پہلے الہام کے ساتھ ہی اس کے دل کو غیر معمولی ثبات عطا کیاجاتا ہے اور اپنے الہام پر سب سے پہلا ایمان لانے والا خود نبی کا وجود ہوتا ہے.اسی وجہ سے ہر نبی اپنے آپ کو اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ(الانعام:۱۶۴) یا اَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ(الاعراف:۱۴۴) قرار دیتا ہے.کیونکہ اگر اسے خود یقین نہ ہو تو وہ دوسروں کے دل میں کس طرح یقین پیدا کرسکتا ہے.چونکہ پہلا یقین خود نبی کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے اس لئے باوجود اس کے کہ بعد میں ساری دنیا مخالف ہوجاتی ہے اور بعض دفعہ انذاری پیشگوئیاں اپنی مخفی یا ظاہر شرائط کی بناء پر ٹل بھی جاتی ہیں اسے ایک لمحہ بھر کے لئے بھی اپنے الہامات کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہوتا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب آتھم والی پیشگوئی کی اورمیعاد کے ختم ہونے کا دن آیا تو مجھے وہ نظارہ اب تک یاد ہے کہ آج کل جہاں حکیم مولوی قطب الدین صاحب کا مطب ہے وہاں لوگ جمع ہوئے اور چیخیں مارمار کر دعائیں کرنے لگے کہ الٰہی یہ پیشگوئی ضرور پوری ہوجائے.ایک پٹھان عبدالعزیز ہوا کرتا تھا وہ تو دیوار کے ساتھ
Page 59
بے تحاشا اپنا سر مارتا اور کہتا خدایا اب یہ سورج نہ ڈوبے جب تک آتھم نہ مرجائے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کا علم ہوا تو آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ چیخیں مار مار کر انہوں نے آسمان سر پر اٹھالیا ہے اگر جھوٹے ہوں گے تو ہم ہوں گے ان کو کس بات کا فکر ہے.اب دیکھو جماعت کے لوگ گھبرارہے تھے مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں تھی.اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان سے صرف کلام سنا تھا ملائکہ کے نزول کی وجہ سے جو ثباتِ قلب عطا کیا جاتا ہے وہ ان کو حاصل نہیں تھا.لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قلب کو غیر معمولی ثبات حاصل تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ چیخ و پکار بے معنی بات ہے جس خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا ہے وہ اپنے کلام کو آپ پورا کرے گا اور اگر کسی شرط کی وجہ سے وہ ٹل جائے گا تب بھی کیا ہوا انذاری پیشگوئیوں کے متعلق جو سنت چلی آرہی ہے بہرحال اسی کے مطابق ہوگا اس لئے گھبراہٹ اور فکر کی کوئی بات نہیں.پس اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خواہ وہ بلا واسطہ نازل ہو فرشتوں کا آنا ضروری ہوتا ہے.مگر یہ خیال کرلینا کہ ہر کلام کے ساتھ فرشتہ آکر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلاں بات پہنچاتا ہوں بالکل غلط ہے.حدیثوں میں بھی صرف پانچ سات ایسی مثالیں مل سکتی ہیں جن میں اَ تَانِیْ جِبْـرِیْلُ کے الفاظ آتے ہوں مگر اور کسی جگہ یہ ذکر نہیں آتا یا رمضان کے متعلق آتا ہے کہ ان ایام میں جبریل آتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے مگر یہ صورت بالکل اور ہے.اس میں جبریل کی حقیقت محض ایک سامع کی ہوتی تھی اور جبریل کا آنا اس لئے ضروری تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن کریم کا ہرلفظ یاد رکھنا ضروری تھا.باقی لوگ اگر قرآن کریم پڑھنے میں کوئی غلطی کرتے تو اور لوگ اس کی اصلاح کرسکتے تھے لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلطی کرتے تو لوگ کس طرح درست کرتے وہ سمجھتے کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رنگ میں کلام نازل ہوا ہے یا پہلے کلام میں کوئی تبدیلی ہوگئی ہے.اس لئے خدا تعالیٰ نے جبریل کو سامع بنادیا تاکہ اگر تلاوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہوجائے تو جبریل آپ کو بتادیں اور آپ اس کی اصلاح کرلیں.پس یہ صورت بالکل اور ہے اس سے یہ استدلال نہیں ہوسکتا کہ ہر کلام کے ساتھ اس رنگ میں فرشتے کا نازل ہونا ضروری ہے کہ وہ آکر یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں بات آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے.ایسا طریق صرف بعض الہامات میں اختیار کیا جاتا ہے باقی الہامات کے ساتھ فرشتوں کا نزول صرف اتنا مفہوم رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام فرشتوں کی حفاظت میں نازل فرماتا ہے.
Page 60
جھوٹے مدعی کی علامت پھر امام راغب لکھتے ہیں وَقَوْلُہٗ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَ لَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌفَذَالِکَ لِمَنْ یَّدَّعِیْ شَیْئًا مِّنْ اَنْوَاعِ مَا ذَکَرْنٰہُ مِنَ الْوَحْیِ اَیَّ نَوْعٍ اِدَّعَاہُ مِنْ غَیْرِ اَنْ حَصَلَ لَہٗ.یعنی یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے.حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ ہوئی ہو.اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ فَذَالِکَ لِمَنْ یَّدَّعِیْ شَیْئًا مِّنْ اَنْوَاعِ مَا ذَکَرْنٰہُ مِنَ الْوَحْیِ.یہ وعید اس شخص کے بارہ میں ہے جو وحی کے متعلق ہماری بیان کردہ قسموں میں سے کسی شق کے ماتحت آجائے اور دعویٰ کرے کہ مجھ پر فلاں قسم کی وحی نازل ہوتی ہے.اَیَّ نَوْعٍ اِدَّعَاہُ مِنْ غَیْرِ اَنْ حَصَلَ لَہٗ.یہ سوال نہیں ہوگا کہ فلاں قسم کی وحی کے متعلق اس نے دعویٰ کیا ہے اور فلاں قسم کی وحی کے متعلق اس نے دعویٰ نہیں کیا.اوپر کی بیان کردہ قسموں میں سے خواہ کسی قسم کی وحی کا وہ دعویٰ کرے اور اس کی حالت یہ ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہوتی ہو تو بہرحال وہ اس آیت کے ماتحت آجائے گا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوگا.یہ ایک نہایت ہی لطیف بات ہے جو مفردات والوں نے بیان کی ہے.ان کا مطلب یہ ہے کہ لغت نے تو وحی کے کئی معنے بیان کئے ہیں جن میں سے بعض ایسے ہیں جن کا وحی الٰہی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں جیسے اشارہ یا ایماء وغیرہ ہے.اور جب لغت کے اعتبار سے وحی کے کئی ایسے معنے ہیں جن کا وحی الٰہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَ لَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ میں کس قسم کی وحی کا ذکر کیا گیاہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف اس وحی الٰہی کا ذکر کیا گیا ہے جس کی مختلف اقسام کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں.اگر کسی شخص کا دعویٔ وحی و الہام ان شقوں کے ماتحت نہیں آئے گا تو اس پر اس آیت کا اطلاق بھی نہیں ہوگا.یہ آیت صرف اسی شخص پر چسپاں ہوگی جو وحی الٰہی کی بیان کردہ قسموں میں سے کسی قسم کا ادّعا کرتا ہو.یہ ایک لطیف نکتہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہائیوں کو سخت دھوکا لگا ہے.وہ اپنے پاس سے وحی کی ایک تعریف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جب بہاء اللہ اس بات کا مدعی تھا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارے نزدیک وہ جھوٹ اور افتراء سے کام لے رہا تھا تو اس پر عذاب کیوں نہ آیا.حالانکہ عذاب صرف اس شخص پر نازل ہوسکتا ہے جو وحی کے متعلق قرآن کریم کی بیان کردہ قسموں میں سے کسی قسم کا دعویٰ کرے نہ یہ کہ خلافِ قرآن اورخلافِ اسلام اور خلافِ مذہب وحی کی ایک نئی تعریف کرکے اور اپنے آپ کو اس وحی کا مورد قرار دے کر یہ شور مچانا شروع کردے کہ جب میں اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا مدعی ہوں تو مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا.بے شک اللہ تعالیٰ
Page 61
نے مفتری علی اللہ پر عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے مگر بہرحال یہ عذاب اسی شخص پر نازل ہوسکتا ہے جو اس قسم کی وحی کا دعویٰ کرے جس سے سابق انبیاء کی نبوتیں مشتبہ ہونے لگ جائیں.اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھ پر اس قسم کی وحی نازل ہوتی ہے جس قسم کی وحی انبیاء سابقین پرنازل ہوا کرتی تھی.جس طرح آدمؑ سے خدا تعالیٰ نے کلام کیاتھا یا نوحؑ سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا یا ابراہیمؑ سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا یا موسٰی سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا یا عیسٰیؑ سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا.اسی طرح مجھ سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے اور وہ کلام اپنی کیفیت اور کمیت کی رو سے بھی ویسا ہی ہے جیسے انبیاء کا کلام ہوتا ہے تو پھر بے شک اس کے جھوٹے ہونے کی صورت میں خطرہ ہوسکتا ہے کہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں اور بے شک اس وقت ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے ہلاک کرے.لیکن اگر وہ وحی کی اپنے پا س سے ایک نئی تشریح کرتا ہے اور اس نئی قسم کی وحی کا اپنے آپ کو مورد قرار دیتا ہے تو وہ قرآنی وعید کے ماتحت نہیں آسکتا.بہاء اللہ کی وحی اس کے دل کے خیالات کا نام ہے جیسے بہائیوں کی حالت ہے کہ ان کے نزدیک وحی صرف قلبی خیالات کا نام ہے.وہ بہاء اللہ کی نسبت لفظی الہام کے قائل نہیں ہیں الا ماشاء اللہ.وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو بھی خیال پیدا ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے.یہی حال لاہور کے میاں غلام محمد کا ہے کہ وہ بھی اپنے دل کے خیالات کا نام وحی رکھ لیتے ہیں.اب اگر دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرے دل میں جو بھی خیال اٹھتا ہے وہ وحی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اسے سزا دینے کی کیا ضرورت ہے.ہر شخص ایسے مدعی کا پاگل ہونا آسانی سے سمجھ سکتا ہے.اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کی تو تب ضرورت محسوس ہو جب کسی کے دعویٔ وحی و الہام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مشتبہ ہونے لگے یا موسٰی اور عیسٰیؑ کی وحی کا معاملہ مشتبہ ہونے لگے اور یہ معاملہ اسی وقت مشتبہ ہوسکتا ہے جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر اسی رنگ میںکلام نازل ہوتا ہے جس رنگ میں کلام موسٰی پر نازل ہوا.یا مجھ پر اسی رنگ میںکلام نازل ہوتاہے جس رنگ میں عیسٰیؑ پر کلام نازل ہوا.یا مجھ پر اسی رنگ میں کلام نازل ہوتا ہے جس رنگ میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوا.جب تک کوئی شخص اس قسم کی وحی کا اپنے آپ کو مورد قرار نہیں دیتا اس کے دعویٰ سے کوئی حقیقی خطرہ پیدا نہیں ہوتا.پس اس کا لازماً الٰہی گرفت میں آنا بھی ضروری نہیں ہوتا.پس مفردات والے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تقوّل اور افتراء علی اللہ سے کام لینے والوں کے لئے جس عذاب کی خبر دی گئی ہے وہ اسی صورت میں نازل ہوسکتا ہے جب کوئی شخص جھوٹے طور پر اس وحی کا دعویٰ کرے جس کی مختلف اقسام کا ہم اوپر ذکر کرچکے ہیں.ان میں سے خواہ کسی قسم کا وہ مدعی بن جائے اللہ تعالیٰ اسے یقیناً عذاب
Page 62
دے گا.مثلاً وہ یہی کہہ دے کہ مجھ سے جبریل اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تھا یا کہے کہ الفاظ معینہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں یا یہ کہے کہ حالت منام میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف باتیں بتائی جاتی ہیں اور واقعہ یہ ہو کہ نہ جبریل اس سے کلام کرتا ہو نہ الفاظ معینہ اس پر نازل ہوتے ہوں نہ تمثیلی نظاروں میں اسے غیب کی خبروں سے مطلع کیاجاتا ہو تو ایسا شخص یقیناً قرآنی وعید کے ماتحت آئے گا.لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جو بھی خیال اٹھتا ہے وہ وحی ہے تو چونکہ یہ قرآنی وحی کی قسموںمیںشامل نہیں اور چونکہ اس طریق سے نہ کسی نبی کی نبوت مشتبہ ہوتی ہے اور نہ کسی دانا شخص کو دھوکا لگ سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو اسے عذاب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی.ہرانسان اپنی عقل سے کام لے کر فوراً فیصلہ کرسکتا ہے کہ وہ پاگل ہے یا شرارتی.اس میں دھوکا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا.ہاں اگر وہ یہ کہے کہ مجھ پر جبریل نازل ہوتا ہے اور وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچاتا ہے یا کہے کہ خدا تعالیٰ میرے کانوں پر یا میری زبان پر معین الفاظ میں اپنا کلام نازل کرتا ہے یا حالت منام میں غیب کی خبروں سے اطلاع دیتا ہے تب بے شک اس پر عذاب نازل ہوگا.یہ بہت عمدہ استدلال ہے جو مفردات والوں نے کیا ہے.وحدانیت کی وحی کے متعلق امام راغب کا خیال اور اس کی تردید پھر لکھتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ (الانبیاء:۲۶) ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم ہمیشہ اس کی طرف یہ وحی نازل کرتے رہے ہیں کہ سوائے میرے اور کوئی خدا نہیں تم ہمیشہ میری ہی عبادت کیاکرو.فَھٰذَا الْوَحْیُ ھُوَ عَامٌّ فِیْ جَـمِیْعِ اَنْوَاعِہٖ وَذَالِکَ اَنَّ مَعْرِفَۃَ وَحْدَانِیَّۃِ اللہِ تَعَالٰی وَمَعْرِفَۃَ وُجُوْبِ عِبَادَتِہٖ لَیْسَتْ مَقْصُوْرَۃً عَلَی الْوَحْیِ الْمُخْتَصِّ بِاُولِی الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ بَلْ یُعْرَفُ ذَالِکَ بِالْعَقْلِ وَالْاِلْھَامِ کَمَا یُعْرَفُ بِالسَّمْعِ فَاِذَا الْقَصْدُ مِنَ الْاٰیَۃِ تَنْبِیْہٌ اَنَّہٗ مِنَ الْمَحَالِ اَنْ یَّکُوْنَ رَسُوْلٌ لَا یَعْرِفُ وَحْدَانِیَّۃَ اللہِ وَوُجُوْبَ عِبَادَتِہٖ.یعنی اس آیت میں جو وحی کا لفظ ہے اس سے لفظی وحی مراد نہیں بلکہ انبیاء کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا مادہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ مراد ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس فطرتی مادہ کے مطابق ہر نبی کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی.گویا ان کے نزدیک اس جگہ وحی سے مخصوص وحی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی فطرت میں یہ مادہ رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور شرک کے کبھی قریب بھی نہ جائے.مگرمیرے نزدیک یہ معنے بالکل غلط ہیں.اگر توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء کی طرف مخصوص وحی نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ
Page 63
وہی فطرتی مادہ کافی ہوتا ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیاجاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں ایسی بیسیوںآیات نازل ہوئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ بڑے زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے؟ یہ امر ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا.چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مشرکین مکہ میں سے بعض آدمیوں نے آپ کے سامنے کچھ کھانا رکھا مگر چونکہ وہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا آپ نے اس کے کھانے سے انکار کردیا اور زید بن عمرو کی طرف سرکادیا جو حضرت عمرؓ کے چچازاد بھائی تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے.مگر انہوں نے بھی وہ کھانا نہ کھایا بلکہ قریش کو مخاطب کرکے کہا کہ ہم بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے.(اسد الغابۃ زیر لفظ زید بن عمرو) اس سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ہی توحید کے قائل تھے اور شرک کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے مگر اس کے باوجود قرآن کریم میں توحید کا مضمون آیا ہے.قرآن کریم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ توحید کے مضامین سے بھرا پڑا ہے اور اس میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا ذکر آتا ہے.پس یہ معنے جو مفردات والوں نے کئے ہیں صحیح نہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انبیاء کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مادہ پیدا کردیا جاتا ہے کہ وہ طبعی طور پر شرک سے متنفر ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف توحید کے متعلق کسی وحی کے نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.باوجود اس کے کہ وہ ذاتی طور پر توحید کے قائل ہوتے ہیں شرک سے متنفر ہوتے ہیں.اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے سربسجود ہونے کو جائز نہیں سمجھتے پھر بھی ان کی طرف توحید کے متعلق وحی نازل کی جاتی ہے اور قرآن کریم میں اس کی بیسیوں مثالیں ملتی ہیں.اس کے بعد لکھتے ہیں وَقَوْلُہٗ تَعَالٰی وَ اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ فَذَالِکَ وَحْیٌ بِوَاسِطَۃِ عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ.اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ.میں نے حواریوں کی طرف وحی کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر حواری کو رات کے وقت الگ الگ وحی ہوئی تھی کہ اٹھ میاں! ہمارے نبی کی مدد کر.بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی اور انہوں نے وہ وحی حواریوں تک پہنچادی یہ با ت واقعہ میں درست ہے اور اس آیت کا یہی مطلب ہے.وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ فَذَالِکَ وَحْیٌ اِلَی الْاُمَمِ بِوَاسِطَۃِ الْاَنْبِیَاءِ.اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ نیک کام کریں یہ وحی امتوں کی طرف ان کے انبیاء کے واسطہ سے تھی.میرا خیال ہے کہ اس موقعہ پر مفردات والوں نے قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھا ورنہ وہ ایسا نہ لکھتے.انہوں نے اِلَيْهِمْ کے لفظ سے یہ سمجھ لیا کہ اس سے تمام بنی نوع انسان مراد ہیںحالانکہ یہ درست نہیں.یہ آیت سورئہ انبیاء میں آتی ہے اور وہاں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام کا
Page 64
دے گا.مثلاً وہ یہی کہہ دے کہ مجھ سے جبریل اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تھا یا کہے کہ الفاظ معینہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں یا یہ کہے کہ حالت منام میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف باتیں بتائی جاتی ہیں اور واقعہ یہ ہو کہ نہ جبریل اس سے کلام کرتا ہو نہ الفاظ معینہ اس پر نازل ہوتے ہوں نہ تمثیلی نظاروں میں اسے غیب کی خبروں سے مطلع کیاجاتا ہو تو ایسا شخص یقیناً قرآنی وعید کے ماتحت آئے گا.لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جو بھی خیال اٹھتا ہے وہ وحی ہے تو چونکہ یہ قرآنی وحی کی قسموںمیںشامل نہیں اور چونکہ اس طریق سے نہ کسی نبی کی نبوت مشتبہ ہوتی ہے اور نہ کسی دانا شخص کو دھوکا لگ سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو اسے عذاب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی.ہرانسان اپنی عقل سے کام لے کر فوراً فیصلہ کرسکتا ہے کہ وہ پاگل ہے یا شرارتی.اس میں دھوکا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا.ہاں اگر وہ یہ کہے کہ مجھ پر جبریل نازل ہوتا ہے اور وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچاتا ہے یا کہے کہ خدا تعالیٰ میرے کانوں پر یا میری زبان پر معین الفاظ میں اپنا کلام نازل کرتا ہے یا حالت منام میں غیب کی خبروں سے اطلاع دیتا ہے تب بے شک اس پر عذاب نازل ہوگا.یہ بہت عمدہ استدلال ہے جو مفردات والوں نے کیا ہے.وحدانیت کی وحی کے متعلق امام راغب کا خیال اور اس کی تردید پھر لکھتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْۤ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ (الانبیاء:۲۶) ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم ہمیشہ اس کی طرف یہ وحی نازل کرتے رہے ہیں کہ سوائے میرے اور کوئی خدا نہیں تم ہمیشہ میری ہی عبادت کیاکرو.فَھٰذَا الْوَحْیُ ھُوَ عَامٌّ فِیْ جَـمِیْعِ اَنْوَاعِہٖ وَذَالِکَ اَنَّ مَعْرِفَۃَ وَحْدَانِیَّۃِ اللہِ تَعَالٰی وَمَعْرِفَۃَ وُجُوْبِ عِبَادَتِہٖ لَیْسَتْ مَقْصُوْرَۃً عَلَی الْوَحْیِ الْمُخْتَصِّ بِاُولِی الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ بَلْ یُعْرَفُ ذَالِکَ بِالْعَقْلِ وَالْاِلْھَامِ کَمَا یُعْرَفُ بِالسَّمْعِ فَاِذَا الْقَصْدُ مِنَ الْاٰیَۃِ تَنْبِیْہٌ اَنَّہٗ مِنَ الْمَحَالِ اَنْ یَّکُوْنَ رَسُوْلٌ لَا یَعْرِفُ وَحْدَانِیَّۃَ اللہِ وَوُجُوْبَ عِبَادَتِہٖ.یعنی اس آیت میں جو وحی کا لفظ ہے اس سے لفظی وحی مراد نہیں بلکہ انبیاء کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا مادہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ مراد ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس فطرتی مادہ کے مطابق ہر نبی کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی.گویا ان کے نزدیک اس جگہ وحی سے مخصوص وحی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی فطرت میں یہ مادہ رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور شرک کے کبھی قریب بھی نہ جائے.مگرمیرے نزدیک یہ معنے بالکل غلط ہیں.اگر توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء کی طرف مخصوص وحی نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ
Page 65
پیغامیوں کے ساتھ ایک نزاع کا فیصلہ پیغامیوں کی طرف سے ہمیشہ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ نبی کسی کا متبع نہیں ہوتا.(النبوۃ فی الاسلام صفحہ ۴۳) میں نے اس کے جواب میں انہیں بارہا کہا ہے کہ تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے تم حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف دیکھو وہ نبی تھے مگر باوجود نبی ہونے کے حضر ت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے.پس تمہاری یہ بات درست نہیں کہ نبی کسی کا تابع نہیں ہوسکتا.اگر درست ہوتی تو حضرت ہارونؑ موسٰی کے کس طرح متبع ہوجاتے.ہارونؑ تو موسٰی کے اس قدر متبع تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے اور ان کی قوم شرک میں مبتلا ہوگئی تو وہ سخت ناراضگی اور غضب کی حالت میں واپس آئے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے نہایت سختی کے ساتھ کہا کہ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ(طٰہٰ:۹۴) کیا میرے صریح حکم کی اس طرح خلاف ورزی کی جاتی ہے؟ اگر وہ متبع نہ ہوتے تو حضرت موسٰی ان پر کس طرح خفا ہوسکتے تھے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خفا ہونا اور ان سے جواب طلب کرنا بتاتا ہے کہ وہ موسٰی کے تابع تھے.پس یہ صحیح نہیں کہ نبی کسی کا تابع نہیں ہوسکتا.پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ہارونؑ موسٰی کے تابع نہیں تھے تو دونوں پر وحی کس طرح نازل ہوتی تھی؟ اس کے جواب میں غیر مبائعین یہ کہا کرتے ہیں کہ دونوں پر برابر وحی نازل ہوتی تھی.جو وحی موسٰی پر ہوتی تھی وہی وحی ہارونؑ پر بھی نازل کردی جاتی تھی.تورات بھی دونوں پر اترتی تھی.ادھر موسٰی پر تورات کا نزول ہوتا تھا اور ادھر ہارونؑ پر تورات کا نزول ہوتا تھا.یہ بات اتنی احمقانہ ہے کہ اسے سن کر حیرت آتی ہے کہ ایک ہی وقت ایک ہی کلام دو مختلف انسانوں پر بغیر کسی حکمت کے نازل کیا جاتا ہو.گویا نعوذباللہ خدا تعالیٰ کو شبہ تھا کہ ایسا نہ ہو میں کسی ایک کی طرف وحی نازل کروں تو وہ دوسرے کو جھوٹ بول کر کچھ اور بتادے.اس لئے خدا تعالیٰ کو یہ احتیاط کرنی پڑی کہ ادھر موسٰی پر وہ کلام نازل کرتا اور ادھر ہارونؑ پر نازل کرتا تاکہ اگر موسیٰ جھوٹ بولے تو ہارون پکڑ لے اور ہارون جھوٹ بولے تو موسیٰ پکڑلے.مگر مفردات والوں نے اس مسئلہ کو بالکل صاف کردیا ہے.وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو یہ آیت آتی ہے کہ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی اس سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ مراد ہے کہ موسیٰ کو الگ وحی کی اور ہارون کو الگ.تورات ادھر موسیٰ پر نازل کی جاتی تھی اور ادھر ہارون پر یا اس سے کچھ اور مراد ہے.وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مرا یہ ہے کہ موسیٰ کی طرف جو وحی ہوتی تھی وہ جبریل کے واسطہ سے تھی یعنی موسٰی پر جبریل کی حفاظت میں وحی نازل ہوتی تھی.اس کے بعد موسٰی وہ بات ہارونؑ تک پہنچادیتے تھے اور موسیٰ کی معرفت اس الہام کا ہارون تک پہنچ جانا ہی ہارون کی وحی تھا.مگر چونکہ ہارون خود بھی نبی تھے اس لئے کبھی کبھی انہیں اپنے طور پر بھی الہام ہوجاتا تھا.مگر وہ الہامات جو شریعت اور احکام کے ساتھ
Page 66
تعلق رکھتے تھے وہ براہِ راست موسیٰ کو ہی ہوتے تھے.اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان احکام کو حضرت ہارونؑ تک پہنچاتے تھے.گویا ہارون موسیٰ کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے تھے کہ مجھے آج فلاں وحی ہوئی ہے.آپ اس کے مطابق عمل کریں.ہاں موسیٰ یہ حق رکھتے تھے کہ ہارون کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے باخبر کریں اور انہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی تاکید کریں.البتہ ہارون چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اس لئے بعض دفعہ ان پر بھی وحی نازل ہوجاتی تھی مگر ایسی ہی جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا.آخر وحی کی صرف اتنی ہی غرض تو نہیں ہوتی کہ اس میں شریعت کے احکام بیان کئے جائیں.بلکہ وحی اس لئے بھی نازل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس کے ایمان کو ترقی دینا چاہتا ہے، اس کے عرفان اور یقین میں زیادتی پیدا کرنا چاہتا ہے.پس ہارون چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اس لئے بعض دفعہ ان پر بھی اس قسم کی وحی نازل ہوجاتی تھی جو غیرتشریعی ہوتی اور جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتا.مگر بہرحال شرعی وحی صرف موسٰی پر نازل ہوتی تھی اور حضرت موسٰی وہ وحی ہارونؑ کو سنادیتے.غرض مفردات والوں نے اس آیت کی تشریح میں تابع اور متبوع کا فرق بیان کردیا ہے اور وہ مسئلہ جس میں ہمارا پیغامیوں سے دیر سے نزاع چلا آرہا ہے اس کا نہایت عمدگی کے ساتھ فیصلہ کردیا ہے.وَ قَوْلُہٗ اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓىِٕكَةِ اِنِّيْ مَعَكُمْ فَذَالِکَ وَحْیٌ اِلَیْـھِمْ بِوَسَاطَۃِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ.اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ تیرا رب ملائکہ کی طرف وحی کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اِنِّيْ مَعَكُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں.یہ وحی ان کی طرف لوح و قلم کے واسطہ سے ہوتی ہے.اس کے بعد کہتے ہیں فِیْـمَا قِیْلَ یعنی بعض لوگوں کا یہی خیا ل ہے مجھے تو اس عقیدہ کے ساتھ اتفاق نہیں مگر پرانے مفسرین کا یہی خیال تھا کہ خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو حکم دیا اور اس نے لوح پر وہ سب کچھ لکھ دیا جو دنیا میںہونے والا تھا.اب ملائکہ جو کچھ پہنچاتے ہیں وہ اسی لوح سے ماخوذ ہوتا ہے.گویا ان کے نزدیک وحی کا پہلا نزول قلم پر ہوا.قلم سے لوح پر لکھا گیا اور پھر لوح سے ملائکہ اخذ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق اس کے احکام اور پیغام دنیا میں پھیلاتے ہیں.میرے نزدیک یہ عقیدہ ایسا ہے جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے تردید ہوتی ہے.مثلاً حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اس کے بعد جبریل اور فرشتوں کو اطلاع دیتا ہے.وہ فرشتے اور فرشتوں کو خبر دیتے ہیں.یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ بات تمام فرشتوں میں پھیل جاتی ہے اور اس شخص کی لوگوں میں مقبولیت پیدا ہوجاتی ہے.(بخاری کتاب الادب باب المقۃ من اللہ تعالٰی )
Page 67
اگر لوح پر ہی سب کچھ لکھا ہوا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو جبریل سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی وہ خودبخود لوح سے تمام حالات معلوم کرسکتے ہیں.بہرحال یہ پرانے مفسرین کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی وحی قلم پر نازل کی، قلم سے لوح پر لکھا گیا اور لوح سے فرشتے پڑھ پڑھ کر بندوں پر وحی نازل کرتے ہیں.وَقَوْلُہٗ وَاَوْحٰی فِیْ کُلِّ سَـمَاءٍ اَمْرَھَا فَاِنْ کَانَ الْوَحْیُ اِلٰی اَھْلِ السَّمَاءِ فَقَطْ فَالْمُوْحٰی اِلَیْـھِمْ مَـحْذُوْفٌ ذِکْرُہٗ کَاَنَّہٗ قَالَ اَوْحٰی اِلَی الْمَلٰئِکَۃِ لِاَنَّ اَھْلَ السَّمَاءِ ھُمُ الْمَلٰئِکَۃِ وَیَکُوْنُ کَقَوْلِہٖ اِذْ یُوْحِیْ رَبُّکَ اِلَی الْمَلٰئِکَۃِ وَ اِنْ کَانَ الْمُوْحٰی اِلَیْہِ ھِیَ السَّمٰوٰتُ فَذَالِکَ تَسْخِیْـرٌ عِنْدَ مَنْ یَّـجْعَلُ السَّمَاءَ غَیْـرَ حَیٍّ وَ نُطْقٍ عِنْدَ مَنْ جَعَلَہٗ حَیًّا.اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا اللہ تعالیٰ نے ہر سماء میں وحی کے ذریعہ اپنا حکم بھیج دیا.اگر اس آیت میں سماء سے اہل سماء مراد لئے جائیں تو چونکہ اہل سماء ملائکہ ہوتے ہیں اس لئے عربی زبان میں اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اَوْحٰی اِلَی الْمَلٰئِکَۃِ اُمُوْرًا مُّتَعَلِّـقًا بِالسَّمَاءِ.اس نے ملائکہ کی طرف ان امور کے بارہ میں وحی کی جن کا آسمان کے ساتھ تعلق تھا.اس مفہوم کی صورت میں قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس کے ہم معنی سمجھی جائے گی کہ اِذْ یُوْحِیْ رَبُّکَ اِلَی الْمَلٰئِکَۃِ لیکن اگر کوئی شخص مُوْحٰی اِلَیْہِ سے مراد سماوات لے تو ان کے متعلق بھی یہ کلام ہوسکتا ہے مگر اس صورت میں حذفِ اضافت کی ضرورت نہیں ہوگی.بلکہ سماوات کو موحٰی الیہ تسلیم کرنے کی صورت میں اس کے د۲و معنے ہوں گے.وہ جن کے نزدیک سماوات کوئی زندہ وجود نہیں.وہ تو اس سے تسخیر مراد لیتے ہیں یعنی اَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں کے متعلق سماوات کو مسخر کردیا ہے اور اسی تسخیر کو وحی قرار دیا گیاہے.لیکن وہ لوگ جو آسمانوں کو زندہ وجود قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک اس کے معنے تسخیر کے نہیں بلکہ یہ مراد ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے ان سے کلام کیا.وَقَوْلُہٗ بِاَنَّ رَبَّکَ اَوْحٰی لَھَا فَقَرِیْبٌ مِّنَ الْاَوَّلِ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے متعلق فرمایا ہے کہ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا اس میں وحی کے معنے تسخیر کے ہی کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ زمین بولتی نہیں اور نہ اس میں عقل پائی جاتی ہے.پس چونکہ زمین کی طرف بولنا منسوب کردیاگیا ہے حالانکہ وہ بولتی نہیں اور اس کی طرف عقل منسوب کردی گئی ہے حالانکہ اس میں عقل نہیں.اس لئے یہ حالات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم یہاں مجازی معنے مراد لیں اور سمجھ لیں کہ اس جگہ وحی سے وحیٔ حقیقی یا وحیٔ لفظی مراد نہیں بلکہ اَوْحٰی کا لفظ زمین کو مسخر کرنے کے معنے میں استعمال ہوا ہے.(مفردات) وحی کی اقسام کے متعلق نصّ قرآنی وحی کے معنے عربی زبان میں تو اوپر بیان ہوچکے ہیں.اب میں اپنے معنے
Page 68
بیان کرتا ہوں.قرآن کریم اور احادیث کے مطالعہ نیز صاحب تجربہ لوگوں کی شہادت سے اس امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ وحی کئی اقسام کی ہوتی ہے.سب سے پہلے ہمیں یہ امر مدّ ِنظر رکھنا چاہیے کہ اس بارہ میں ایک نصِّ قرآنی موجود ہے جو یہ ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ١ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ (الشورٰی:۵۲) اس آیت کے میرے نزدیک مفسرین نے صحیح معنے نہیں سمجھے جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ کے غلط معنے لے لئے ہیں.انہوں نے وحی کے معنے منام اور تسخیر وغیرہ کے کردیئے ہیں اور وَرَآئِ حِجَابٍ کے یہ معنے کرلئے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نظر نہ آتا ہو جس کی مثال میں وہ موسٰی کا کلام پیش کرتے ہیں اور يُرْسِلَ رَسُوْلًا کے معنے یہ کئے ہیں کہ جب جبریل کلام کے ساتھ آئے اور وہ نظر بھی آئے.آخری صورت میں ہمارا اور ان کا اس فرق سے اتفاق ہے کہ ہم جبریل کے ذریعہ سے کلام آنے کو تو صحیح تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہر ایسی وحی کے نزول کے وقت جبریل نظر بھی آتا ہے.چند مثالوں پر دھوکا کھاکر یہ غلط قیاس کرلیا گیا ہے.پہلی اور دوسری صورت پر ہمیں کلی طور پر اعتراض ہے.پہلی صورت پر تو یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم میں پینسٹھ دفعہ وحی کا لفظ اِلٰى کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے.مگر کہیں بھی قرآن کریم میں وحی کا لفظ محض تصویری زبان کے معنوں میں نہیں آیا.بے شک بعض جگہ مجازی معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جیسے ایک جگہ وحی کے معنے تسخیر کے آگئے ہیں.لیکن ان مجازی معنوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے جہاں بھی وحی کا لفظ آیا ہے ایسے ہی اظہار کے متعلق آیا ہے جس کے ساتھ کلام بھی تھا.اب کیا یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر کریں اور وحی پر بحث کرتے ہوئے پینسٹھ جگہ جن معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان معنوں کو تو نہ لیں اور وحی کے معنے خالص تصویری زبان کے کرلیں.ان پینسٹھ مقامات کے علاوہ پانچ اور بھی جگہیں ہیں جہاں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں بھی بمعنے کلام ہی استعمال ہوا ہے صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں وحی کے معنے تسخیر کے علاوہ اور کچھ نہیں کئے جاسکتے اور وہ جگہ وہی ہے جہاں شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ (النحل:۶۹) یعنی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی.اس آیت کو مستثنیٰ کرتے ہوئے کہ اس میں وحی کا لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے باقی سارے قرآن میں ہرجگہ وحی کا لفظ ایسے ہی اظہار کے متعلق استعمال ہوا ہے جس کے ساتھ کلام بھی ہو.اور جب ہر جگہ قرآن کریم یہی معنے مراد لیتا ہے تو یہ کیسی عجیب بات ہوگی کہ جن معنوں میں قرآن کریم اس لفظ کا استعمال کرتا ہے ان معنوں کو تو ہم نہ لیں اور اس کے اور معنے کرنے شروع کردیں.یہ تو ہوسکتا ہے کہ جب کوئی مجبوری پیش آئے تو ہم اس کے معنوں میں مجاز اور استعارہ مراد لے لیں
Page 69
مگر یہ نہیں ہوسکتا کہ ہمیں کوئی مجبوری بھی پیش نہ آئے اور ہم قرآن کریم کے استعمال کو کلی طور پر نظر انداز کرکے ان معنوں کو لے لیں جو قرآن کریم نے کسی ایک جگہ بھی نہیں کئے.مفسرین کی وَرَآ ئِ حِجَابٍ کلام کرنے کی غلط تشریح مفسرین کی یہ تشریح کہ اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ سے مراد موسیٰ کا کلام ہے.یہ بھی کسی رنگ میں قابل قبول نہیں سمجھتی جاسکتی.کیونکہ اِلَّا وَحْيًا کے بعد اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ کے معنے اگر ہم موسٰی کے کلام کے کریں تو اس کے معنے یہ بنیں گے کہ موسٰی پر وحی نہیں ہوئی حالانکہ موسٰی کا کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کرتے ہوئے سب سے مقدم وحی ہے.جسے کسی صورت میں بھی دائرہ وحی سے خارج نہیں کیاجاسکتا.پھر عجیب بات یہ ہے کہ خود یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اِنْقَطَعَ الْوَحْیُ وَبَقِیَتِ الْمُبَشِّـرَاتُ رُؤْیَا الْمُؤْمِنِ.وحی منقطع ہوگئی ہے صر ف مبشرات باقی رہ گئے ہیں جس سے مراد وہ سچے رؤیا ہیں جو مومن کو دکھائے جاتے ہیں.یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو اوّل درجہ دیا ہے اور منام کو دوسرا درجہ.اگر جیسا کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے منام کا نام ہی وحی ہوتا تو پھر بجائے یہ کہنے کے کہ اِنْقَطَعَ الْوَحْیُ وَبَقِیَتِ الْمُبَشِّـرَاتُ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اِنْقَطَعَ الْکَلَامُ وَرَایَٔ الْـحِجَابِ وَبَقِیَ الْوَحْیُ.وراء حجاب اللہ تعالیٰ جو کلام کیا کرتا تھا وہ منقطع ہوچکا ہے اب صرف وحی باقی رہ گئی ہے جس سے مراد خوابیں وغیرہ ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنْقَطَعَ الْوَحْیُ کہنے کے بعد بَقِیَتِ الْمُبَشِّـرَاتُ فرمایا ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی وحی کے معنے محض منام کے نہیں ہیں.پس ان کے معنے بالبداہت باطل اور قرآنی محاورہ کے خلاف ہیں.حقیقت یہ ہے کہ وحی کے معنے جہاں اشارہ، رمز اور تحریر کے ہیں وہاں ایسے کلام کے بھی ہیں جو دوسروں سے مخفی رکھ کر کیا جائے.چنانچہ لغت سے یہ امر ثابت کیا جاچکا ہے کہ وحی کے معنے اشارہ، رمز اور تحریر کے بھی ہیں اور ایسے کلام کے بھی ہیں جو دوسروں سے مخفی رکھ کر کیا جائے.ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں وحی کا لفظ زیادہ تر مؤخر الذکر معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے پہلے معنے بہت کم استعمال ہوئے ہیں.مثلاً منام کے معنوں میں تو قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی وحی کا لفظ استعمال نہیں ہوا.رمز، اشارہ یا تحریر کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مگر صرف ایک جگہ یعنی حضرت زکریاؑ والی مثال میں رمز کے معنوں میں یا مکھی والی مثال میں تسخیرکے معنوں میں استعمال ہوا ہے.باقی کسی جگہ بھی اشارہ، رمز، تحریر یا تسخیر وغیرہ کے معنے نہیں آئے حالانکہ یہ لفظ قرآن کریم میں ستر۷۰ جگہ استعمال ہوا ہے.
Page 71
اسے بات کے سننے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ نہ اسے شبہ ہوتا ہے نہ بات کرنے والے کو کوئی شبہ ہوتا ہے.اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو مخفی طور پر بندے کے کان یا اس کے دل یا اس کی زبان وغیرہ پر نازل کردیتا ہے.یہ بتانے کے لئے کہ میں اس راز میں دوسروں کو شریک کرنا نہیں چاہتا یا اس کے واسطہ سے یہ کلام دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی قبولیت اور عظمت دنیا میں قائم ہو.ورنہ وہ ویسا ہی یقینی اور قطعی کلام ہوتاہے جیسے د۲و دوست جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کا ایک دوسرے سے کلام کرنا قطعی اور یقینی ہوتا ہے.غرض وحی اس کلام کا نام رکھ کر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بولتا ہے اس میں اور انسانی کلام میں کوئی فرق نہیں.صرف یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو اس طرح پید اکرتا ہے کہ صرف وہی اسے سنے جسے سنانا مقصود ہے ورنہ وہ ویسا ہی یقینی کلام ہے جیسا کہ د۲و بولنے والوں میں استعمال ہوتا ہے.باقی رہے ایسے خواب جو تصویری زبان میں ہوں وہ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ کلام ہوتا ہے یعنی تعبیر طلب.دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور مضمون اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے.وراء حجاب کے معنے بھی یہی ہیں کہ حقیقت ایک پردہ کے پیچھے مستور ہوتی ہے تم اس پردہ کو اٹھائو تو وہ تمہیں نظر آجائے گی بغیر پردہ اٹھانے کے تم اصل حقیقت سے آگاہ نہیں ہوسکتے.گویا وحی کے معنے تو لفظی کلام کے ہیں جس کی غرض اس کلام کو غیروں سے چھپانا ہوتا ہے اور مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ کے معنے یہ ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح کلام کرتا ہے کہ حقیقت کو خود اس شخص کے لئے بھی پردہ کے پیچھے مخفی کردیتا ہے جس پر وہ نازل ہورہا ہوتا ہے.جب تک اس پردہ کو نہ اٹھایا جائے اس وقت تک حقیقت کا انسان کو پورے طور پر علم نہیں ہوسکتا.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے فرعون نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا کہ سات پتلی گائیں سات موٹی گائیں کھا رہی ہیں.اب خواہ تم سارا دن کہتے رہو کہ پتلی گائیں موٹی گائیں کھارہی ہیں.پتلی گائیں موٹی گائیں کھارہی ہیں کوئی دوسرا شخص کچھ بھی نہیں سمجھے گا کہ تمہارا اس کلام سے منشاء کیا ہے.سب تمہاری بات کو سن کر ہنسیں گے کہ پاگل ہوگیا ہے.لیکن پردہ اٹھائو تو اس کے پیچھے یہ حقیقت مخفی ہوگی کہ قحط کے سات سال خوشحالی کے سات سالوں کے جمع کئے ہوئے غلوں کو کھاجائیں گے.پس جس چیز کو متقدمین نے موسٰی کے کلام کی مثال قرار دیا ہے وہ درست نہیں.موسٰی کا کلام وحی میں ہی شامل ہے اور مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ہم کلامِ خفی میں بات کرتے ہیں یعنی وہ شخص تو ہماری بات سن لیتا ہے جس کو سنانا ہمارے مدّ ِنظر ہوتا ہے لیکن دوسرا شخص ہماری بات کو نہیں سن سکتا.اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کلام مشتبہ ہوتا ہے.وہ کلام مشتبہ نہیں بلکہ ویسا ہی یقینی ہوتا ہے جیسے زید اور بکر آپس میں باتیں کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی گفتگو سننے میں
Page 72
کوئی اشتباہ نہیں ہوتا.مگر چونکہ ہم دوسروں کو نہیں سنانا چاہتے اس لئے جس طرح انسان دوسرے کے کان میں بات کہہ دیتا ہے ہم بھی ایسے رنگ میںبات کرتے ہیں کہ صرف وہی شخص سنتا ہے جس کو ہم سنانا چاہتے ہیں دوسرا شخص ہماری بات کو نہیں سن سکتا.ہاںایک فرق ضرور ہے اور وہ یہ کہ کسی کے کان میں بات کرنے والا تو طبعی قوانین سے مجبور ہوتا ہے اور وہ ڈرتاہے کہ اگر میں نے زیادہ زور سے بات کی تو دوسرے لوگ بھی سن لیں گے اس لئے وہ آہستگی سے بات کرتا ہے مگر ہم بلند آواز سے بات کرتے ہیں اور پھر بھی صرف وہی شخص ہماری بات سن سکتا ہے جس پر ہم وحی نازل کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگ ہماری آواز کو نہیں سن سکتے.دوسری صورت یہ ہے کہ ہم رمز سے بات کرتے ہیں یعنی جب تک انسان حجاب نہ اٹھائے اس پر حقیقت منکشف نہیں ہوتی.اس کے بعد اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک وحی ایسی ہوتی ہے جو بالواسطہ آتی ہے ہم اپنے بندے سے بے شک کلام کرتے ہیں مگر براہ راست نہیں بلکہ ہم مَلک رسول سے بات کرتے ہیں اور مَلک رسول آگے بشر رسول سے کرتا ہے مگر بہرحال یہ بھی وحی ہی ہوتی ہے.مَلک رسول کے ذریعہ کوئی بات پہنچانے سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شق وحی کے دائرہ سے خارج ہے اسی لئے يُرْسِلَ رَسُوْلًا کے بعد فَيُوْحِيَ کا لفظ دوہرایا گیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ یہ شق بھی وحی الٰہی میں ہی شامل ہے.اس کے بعد بِاِذْنِهٖ کہہ کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ مَلک رسول اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا ہمارے اذن اور منشاء سے وہ بات پہنچاتا ہے گویا ہے تو وہ بھی کلام مگر اس کلام کے پہنچانے میں ایک واسطہ پیدا کردیا گیا ہے.اس طرح آیت کا لفظ لفظ بالکل اپنے مقام پر کھڑا ہے.مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا الگ چیزہے، اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ الگ چیز ہے اور يُرْسِلَ رَسُوْلًا الگ چیز ہے.یہ تین قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اور تینوں میں اَوْ کالفظ رکھ کر بتایا ہے کہ ان تینوں میں مغائرت پائی جاتی ہے.اِلَّا وَحْيًا سے مراد ہے وَحْیًا بِغَیْرِ الْوَاسِطَۃِ.اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ سے مراد ہے فِی الْمَنَامِ یا بِالْاِشَارَۃِ.اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا سے مراد یُوْحِیْ بِالْوَاسِطَۃِ یعنی اللہ تعالیٰ مَلک رسول کو وحی کرتا ہے اور وہ بشر رسول کو کرتا ہے.چونکہ وحی کی یہ قسم بالواسطہ ہے اور شبہ پیدا ہوسکتا تھا کہ یہ دائرہ وحی سے خارج نہ ہو اس لئے ضروری تھا کہ اس کے ساتھ وضاحت کردی جاتی کہ یہ قسم بھی وحی الٰہی میں شامل ہے چنانچہ اسی لئے فَیُوْحِیَ بِاِذْنِہٖ مَا یَشَاءُ کہہ کر وحی کالفظ اللہ تعالیٰ نے دُہرادیا اور بتادیا کہ یہ شق بھی وحی الٰہی میں شامل ہے.وحی کی تین اقسام غرض اس آیت کے ماتحت وحی کی تین اقسام ہوگئیں.
Page 73
۱) حقیقی بلا واسطہ وحی.کہ خدا تعالیٰ کا کلام بندہ پر بغیر کسی واسطہ کے نازل ہو (۲) دوسری جسے قرآن نے تیسرے درجہ پر رکھا ہے مگر میں تقریب تفہیم کے لئے اسے پہلے بیان کردیتا ہوں وہ حقیقی بالواسطہ وحی ہے جس میں خدا تعالیٰ اپنا کلام فرشتے پر نازل کرتا ہے اور فرشتہ بندے تک پہنچاتا ہے.(۳) تیسری تابع وحی ہے جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے الفاظ نازل نہیں ہوتے بلکہ مضمون کو تعبیر طلب امثال میں یا بے تعبیر طلب نظارہ میں دکھایا جاتا ہے اور اس کو لفظوں میں تبدیل کرنا بندہ کے سپرد کردیا جاتاہے.چونکہ حقیقت حجاب کے پیچھے مخفی ہوتی ہے اس لئے انسان جب تعبیر طلب تمثیل یا نظارہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے قیاس سے کام لے کر حقیقت کو اپنے الفاظ میں بیان کردیتا ہے اور کہتا ہے مجھے خدا نے یوں بتایا ہے.فرض کرو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ تیرا لڑکا کامل ہوجائے گا تو یہ ضروری نہیں کہ خدا نے اسے یہ خبر ان الفاظ میں ہی دی ہو کہ ’’تیرا لڑکا کامل ہوجائے گا‘‘ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نظارہ دکھایا ہو کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کررہا ہے.چونکہ یہ نظارہ مشابہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے اس لئے گو اسے نظارہ یہ دکھایا گیا ہو کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کررہا ہے مگر وہ اسماعیلی واقعہ پر قیاس کرکے اس وراء حجاب کلام کو تعبیری زبان میں بیان کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا لڑکا بہت بڑا مقام حاصل کرنے والا ہے یا وہ بڑے رتبہ پر پہنچ جائے گا.اب جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے وہ اس کے اپنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے ان الفاظ میں خبر نہیں دی کہ ’’تیرا لڑکا کامل ہوجائے گا‘‘ یا ’’ بڑے رتبہ پر پہنچ جائے گا‘‘ اس نے صرف یہ نظارہ دکھایا ہے کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کررہا ہے مگر یہ اس کی تعبیر کرتا اور لوگوں میں اس کا اعلان کردیتا ہے.اب اگر اس کی تعبیر سو فی صدی درست ہو تب بھی وہ قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاہے کہ ’’تیرا بچہ ایک کامل شخص ہوگا‘‘.وہ قسم کھا کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ خدا نے مجھے اس اس رنگ میں نظارہ دکھایا ہے مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ الفاظ بتائے ہیں.یہ وہی شخص کہے گا جس پر لفظاً الہام نازل ہوا ہووہ بے شک قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے ’’تیرا‘‘.مجھے خدا نے کہا ہے ’’بچہ‘‘.مجھے خدا نے کہا ہے ’’بڑا‘‘.مجھے خدا نے کہا ہے ’’آدمی‘‘.مجھے خدا نے کہا ہے ’’ہوجائے گا‘‘ مگر ایسا شخص جس نے صرف نظارہ دیکھا ہے یہ تو قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں مفہوم بیان کررہا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے مگر الفاط کے متعلق قسم نہیں کھاسکتا.چونکہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا مافی الضمیر لفظوں میں ہی بتاسکتا ہے خواہ بول کر خواہ لکھ کر.اس لئے وہ وحی زیادہ شاندار سمجھی جاتی ہے جو الفاظ میں آجائے.خوا ہ لکھے ہوئے الفاظ اس کے سامنے آجائیں.خواہ اسے آواز
Page 74
سنائی دے جس کے معین الفاظ ہوں.خواہ الفاظ اس کی زبان پر یا دل پر جاری کردیئے جائیں (دل میں آئیں نہیں بلکہ جاری کئے جائیں.دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے) اور وہ ایک ایک لفظ کے متعلق قسم کھا کر کہہ سکتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں.اسی طرح خواہ یہ کلام بلاواسطہ نازل ہو یا بالواسطہ کسی مَلک رسول کے ذریعہ سے نازل ہو جب بھی کوئی الٰہی کلام لفظوں میں موجود ہو اور انسان دوسروں کو اس کلام کے معین الفاظ سنا کر کہہ سکتاہو کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئے ہیں تو وہ وحی زیادہ اعلیٰ اور زیادہ شاندار سمجھی جاتی ہے اور جو تعبیری زبان میں وحی نازل ہو یا تصویری زبان میں نازل ہو چونکہ اس کے بیان کرنے میں انسان کو اپنے الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اس میں غلطی کا زیادہ احتمال ہوتا ہے اس لئے اسے پہلی قسم کی دونوں وحیوں سے ادنیٰ سمجھا جاتا ہے.دراصل جس طرح لغت والے کہتے ہیں کہ وضع لغت کے لحاظ سے فلاں لفظ کے یہ معنی ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وضع وحی کے لحاظ سے وحی کے مقدم معنے اس وحی کے ہیں جو الفاظ میں نازل ہو.پھر استعارہ اور مجاز کے طور پر دوسری قسموں کے لئے بھی اس لفظ کا استعمال کرلیتے ہیں.مگر بہرحال یہ دونوں قسم کی وحی پہلی وحی سے ادنیٰ سمجھی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اسے وحی کے نام سے موسوم ہی نہیں کرتے.چنانچہ امت محمدیہ میں جو صوفیاء گذرے ہیں ان کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ صرف وحی لفظی کو وحی کہتے تھے باقی قسموں کو وحی قرا رنہیں دیتے تھے بلکہ خواب یا کشف کہہ دیتے تھے.چنانچہ وحی، کشف اور رؤیا کا لفظ بار بار ان کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ محاورہ اتنی کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے کہ موجودہ زمانہ میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حقیقت کھل جانے کے باوجود ہم بھی اکثر اسی محاورہ کو استعمال کرتے ہیں.بلکہ خود میں نے بارہا اپنی تقریروں اور تحریروں میں وحی، کشف اور رؤیا کے الفاظ استعمال کئے ہیں.چونکہ وحی کا لفظ کثرت سے لفظی کلام کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے صوفیاء نے اس لفظ کو صرف لفظی وحی کے لئے مخصوص کرلیا ہے.باقی قسمیں جو درحقیقت وحی کی ہی مختلف شقیں ہوتی ہیں ان کو وہ وحی قرار نہیں دیتے بلکہ کشف یا رؤیا کہہ دیتے ہیں.پھر بعض لوگ تو اور بھی اونچے چلے گئے ہیں وہ صرف نبی کی وحی کو وحی کہتے ہیں.غیر نبی کی وحی کو وحی نہیں بلکہ الہام قرار دیتے ہیں.ان کے نزدیک اس امتیاز کی بنیاد اس امر پر ہے کہ ان میں سے ایک چیز شبہ سے بالا ہے اور دوسری چیز اپنے اندر شبہ کا احتمال رکھتی ہے.نبی کی وحی چونکہ شبہ سے بالا ہوتی ہے اس لئے وہ اسے وحی کہتے ہیں لیکن غیر نبی کی وحی چونکہ احتمالِ شبہ رکھتی ہے اس لئے وہ اسے وحی نہیں الہام کہتے ہیں.الہام کے معنے گو عام طور پر در دل انداختن کے کئے جاتے ہیں.مگر میں نے خود صوفیاء کی کتابوں میں وہ لفظی وحی دیکھی ہے جو ان کی طرف نازل ہوئی.
Page 75
بعض لوگوں کا وحی و الہام میں غلط طور پر امتیاز کرنا وہ کئی جگہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا اور پھر اس وحی کے معین الفاظ ان کی کتابوں میں درج ہوتے ہیں مگر باوجود لفظوں میں وحی نازل ہونے کے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پر وحی نازل ہوئی ہے بلکہ وہ اس کا نام الہام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اِنَّ الْوَحْیَ مِنْ خَوَاصِ الْاَنْبِیَاءِ الْمُرْسَلِیْنَ وَالْاِلْھَامُ مِنْ خِوَاصِ الْوَلَایَۃِ (وَالثَّانِیْ) اِنَّ الْوَحْیَ مَشْـرُوْطٌ بِالتَّبْلِیْغِ.یعنی وحی کا نزول خاص نبیوں سے جو مرسل ہو تعلق رکھتا ہے اور الہام ولایت کی خصوصیات سے ہے.دوسرے وہ کہتے ہیں کہ وحی کا لفظ اسی کلام کے ساتھ مخصوص ہے جسے انہی الفاظ میں لوگوں تک پہنچانے کا حکم ہو.اس تشریح کے مطابق اگر ان پر لفظی کلام نازل ہو تو وہ اسے الہام کہہ دیتے ہیں.اگر آنکھوں دیکھا نظارہ ہو تو وہ اسے کشف کہہ دیتے ہیں.اور اگر حالت منام میں تصویری زبان میں کوئی نظارہ دکھایا جائے تو وہ اسے رؤیا کہہ دیتے ہیں.بہرحال اپنے مذاق کے مطابق انہوں نے اس کو ایک نئی شکل دے دی ہے.ان کے نزدیک وحی کے معنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ قطعی اور یقینی کلام جو انبیا ء پر نازل ہوتا ہے اور الہام کے معنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کسی غیر نبی پر لفظی کلام کی صورت میں اپنا منشا ظاہر کرنا.چونکہ اس شق کو نہ وہ رؤیا میں شامل کرسکتے تھے نہ کشف میں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نظارہ نہیں ہوتا اور دوسری طرف وہ اس کو وحی بھی قرار نہیںدے سکتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک وحی صرف اسی کلام کو کہا جاسکتا ہے جو انبیا ء پر نازل ہو.اس لئے انہوںنے اس کا ایک نیا نام یعنی الہام رکھ دیا تاکہ نبی اور غیر نبی پر نازل ہونے والے کلام میں ایک امتیاز قائم ہوجائے.بہرحال چونکہ وراء حجاب کلام میں غلطی کا زیادہ احتمال ہوتا ہے اور اس کے بیان کرنے میں انسان کو اپنے الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں اس لئے پہلی قسم کی دونوں وحیوں یعنی حقیقی بلا واسطہ وحی اور حقیقی بالواسطہ وحی سے ادنیٰ سمجھا جاتا ہے.یہاں تک کہ بعض لوگ جیسا کہ میں بتاچکا ہوں اسے وحی کے لفظ سے موسوم ہی نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ہم نے خواب میں ایسا دیکھا ہے یا ہم نے کشف میں فلاں نظارہ دیکھا ہے.پھر خواب یا کشف کا نظارہ اس لئے بھی ادنیٰ سمجھا جاتا ہے کہ خواب یا کشف وحی متلو میں نہیں آسکتا.اعلیٰ سے اعلیٰ وحی متلو وحی ہے اور تصویری زبان کی وحی متلو نہیں ہوسکتی.متلو وحی وہ ہوتی ہے جسے پڑھا جاسکے مگر خواب یا کشف کی صورت میں جب کوئی بات بتائی جائے تو وہ پڑھی نہیں جاسکتی.یہ تو ہوسکتا ہے کہ انسان ایک نظارہ دیکھ لے مگر یہ نہیں ہوسکتا کہ اس نظارہ کو وہ پڑھ سکے یا دوسروں کو پڑھا سکے.وہ اس نظارہ کی کیفیت کو اپنے الفاظ میں بیان کرسکتا ہے مگر یہ نہیں کرسکتا کہ کشف یا خواب کو پڑھ کر سنادے.پڑھ کر وہی چیز سنائی جاسکتی ہے جو کہ الفاظ کی شکل میں ہو نہ کہ نظارہ کی شکل میں.پس وہ وحی جو مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ ہوتی ہے چونکہ اس میں کشفی طور پر ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے یا
Page 76
حالت منام میں کوئی بات تصویری یا تعبیری زبان میں بتائی جاتی ہے اور اسے پڑھا نہیں جاسکتا اس لئے لفظی وحی سے اس کا مقام ادنیٰ سمجھا جاتا ہے اور یہی تمام صاحب تجربہ لوگوں کا قول ہے کہ وحی الٰہی میں سے اعلیٰ مقام وحی لفظی کو حاصل ہے کیونکہ وہ پڑھی جاتی ہے.خواب چونکہ پڑھی نہیں جاتی یا کشف چونکہ پڑھا نہیں جاتا اس لئے اسے لفظی وحی کا جو وحی متلو ہوتی ہے مقام حاصل نہیں ہوسکتا.مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رؤیا میں دیکھا کہ گائیں ذبح کی گئی ہیں(بخاری کتاب التعبیر باب اذا راٰی بقرا تنحر).اب ہم اس کو ویسی ہی قطعی اور یقینی وحی سمجھتے ہیں جیسے آپ پر لفظی وحی نازل ہوئی.مگر سوال تویہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کس طرح آسکتا تھا.کیا گائیوں کی تصویریں قرآن کریم میں بنادی جاتیں اور اس طرح بتایا جاتا کہ یہ نظارہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا؟ اور اگر تصویر ہی بنادی جاتی تو پھر بھی یہ سوال رہ جاتا کہ اس کو پڑھا کس طرح جائے؟ پس چونکہ اس وحی کو پڑھا نہیں جاسکتا اس لئے اسے دوسری وحیوں سے ادنیٰ سمجھا جاتا ہے.ہاں تصویری زبان کی وحی میں بھی بعض خاص فوائد ہوتے ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس وحی کا کیا فائدہ ہے نبی پر ہمیشہ کلام ہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کیوں اس پر کشف یا رؤیا میں بعض دفعہ حالات کا انکشاف کیا جاتا ہے؟ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ وحی کرنے میں بعض حکمتیں اس کا جواب یہ ہے کہ تصویری زبان کی وحی میں بھی بعض ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی ضرورت سے استغناء ظاہر نہیں کیا جاسکتا.مثلاً ایک فائدہ تو اس وحی میں یہ ہے کہ گو کلام میں بھی اجمال کو مدّ ِنظر رکھا جاسکتا ہے مگر تصویری زبان میں تو بعض دفعہ ایسا اجمال ہوتا ہے جو کسی فقرہ میں بھی نہیں ہوسکتا.اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ اگر رؤیا یا کشف کی حالت میں کسی کی صورت آنکھوں کے سامنے پھرادی جائے اس کے ماتھے پر شکن پڑے ہوئے ہوں اور دس بیس مختلف قسم کے جذبات اس کے چہرہ سے عیاں ہورہے ہوں تو یہ نظارہ ایک ساعت میں اسے دکھایا جاسکتا ہے.لیکن اگر انہی جذبات کو الفاظ کی صورت میں اد اکیا جائے تو خواہ کیسے بھی مجمل الفاظ ہوں اور کس قدر اختصار کو ملحوظ رکھا گیا ہو پھر بھی دس پندرہ فقروں میں وہ مضمون ادا ہوگا اور ممکن ہے پھر بھی کوئی خامی رہ جائے.پس ایسے مواقع پر جب اجمال در اجمال صورت میں اللہ تعالیٰ کوئی بات بتانا چاہتا ہو اور الفاظ سے زیادہ بہتر اور مؤثر پیرایہ میں قلیل سے قلیل وقت میں کوئی بات اپنے بندہ پر ظاہر کرنا چاہتا ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ تصویری زبان میں وحی نازل کرتا ہے ایک نظارہ آنکھوں کے سامنے پھرا دیتا ہے اور اس طرح وہ باتیں جو دس بیس فقروں کی محتاج ہوتی ہیں آن کی آن میں انسان پر منکشف ہوجاتی ہیں.اسی طرح تصویری زبان میں وحی نازل کرنے کے اور بھی کئی فوائد ہوتے ہیں مثلاً بعض دفعہ کسی مومن بندے کی استمالت قلب
Page 77
مدّ ِنظر ہوتی ہے جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ کلام کی بجائے تصویری زبان اختیار کرلیتا ہے.فرض کرو اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان کرنا چاہتا ہے کہ گھبرائو نہیں دین کو تقویت حاصل ہوجائے گی اور نبی کا ایک مرید ایسا ہے جس کا نام عبدالقوی ہے تو اللہ تعالیٰ رؤیا یا کشف کی حالت میںعبد القوی اس کو دکھادے گا.اب یہ ظاہر ہے کہ عبدالقوی کو دکھانے سے گو یہ مضمون بھی بیان ہوگیا کہ دین کو تقویت حاصل ہوگی مگر ساتھ ہی عبدالقوی کا دل بھی خوش ہوجائے گا کہ میںبھی اپنے نبی کی خواب میں آگیا ہوں یا مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی ابوبکرؓ کو دیکھا یا عمرؓ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا منشا محض ایک مضمون بیان کرنانہیں تھا بلکہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کی استمالت قلب بھی مدّ ِنظر تھی.اور اللہ تعالیٰ چاہتاتھا کہ وہ خواب سن کر خوش ہوجائیں کہ ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آگئے ہیں.پس بعض دفعہ مضمون بیان کرنے کے علاوہ زائد طور پر کسی مومن کی دلجوئی اور استمالت قلب بھی مدّ ِنظر ہوتی ہے جو تصویری زبان میں وحی نازل کرنے سے پوری ہوجاتی ہے.پس تصویری زبان میں وحی کا نزول بے فائدہ نہیںہوتا بلکہ اس کے کئی اغراض ہوتے ہیں اور کئی فوائد ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ زائد طور پر ظاہر کرنا چاہتا ہے.بے شک وہ فوائد مقصود بالذات نہیں ہوتے صرف ضمنی ہوتے ہیں مگر بہرحال وہ ضمنی فوائد تصویری زبان کے ذریعہ ہی ظاہر ہوسکتے ہیںلفظی کلام کے ذریعہ ظاہر نہیں ہوسکتے.انہی فوائد کی وجہ سے بعض دفعہ اہم معاملات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویری زبان میں دکھائے جاتے ہیں مگر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اسے وحی لفظی میں دوبارہ بیان کردیا جاتا ہے گویا تصویری زبان میں بھی ایک نظارہ دکھادیا جاتا ہے اور کلامی زبان میں بھی اس کو بیان کردیا جاتا ہے.اس طرح دونوں فوائد پیدا کردیئے جاتے ہیں.وہ فوائد بھی جو کلام سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ فوائد بھی جو تصویری زبان سے وابستہ ہوتے ہیں.اس کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اور واقعہ اسراء ہیں کہ دونوں ذرائع سے ان کا اظہار کیا گیا.واقعہ معراج کا حدیثوں میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے اور قرآن کریم نے بھی سورئہ نجم میں اس کو بیان کردیا ہے.اسی طرح واقعہ اسراء تصویری زبان میں بھی آپ کو دکھایا گیا اور سورئہ بنی اسرائیل میں لفظی وحی میں بھی اس کا ذکر کردیا گیا.قرآن کریم میں تو اس کا ذکر اس لئے کردیا گیا کہ یہ واقعہ وحی متلو میں آجائے اور نظارہ آپ کو اس لئے دکھایاگیا کہ جو زائد فوائد تصویری زبان کی وحی سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی حاصل ہوجائیں.مثلاً اگر غور کیاجائے تو واقعہ اسراء کا صرف اتنا مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائے گا.لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظارہ دکھایا گیا کہ جبریل آپ کے پاس براق لائے اور آپ اس پر سوار ہوکر بیت المقدس تک پہنچے اور پھر آپ نے لوگوں کے سامنے یہ
Page 78
بات بیان فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ بیت المقدس سے ہو آئے ہیں تو ہمیں اس کا نقشہ بتائیں جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے انہیں بتایا کہ بیت المقدس ایسا ہے ایسا ہے.تو اس سے لوگوں کے ایمانوں میں جو تازگی پیدا ہوئی ہوگی وہ محض لفظی کلام سے کہاں پیدا ہوسکتی تھی یا مثلاً احادیث میں آتا ہے واپسی کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکہ کی طرف آرہا ہے اور اس قافلہ والوں کا ایک اونٹ گم ہوگیا ہے جس کی وہ تلاش کررہے ہیں.آپ نے یہ بات بھی کفار کے سامنے بیان کردی.چنانچہ چند دن بعد معلوم ہوا کہ بعینہٖ یہ واقعہ مکہ کے ایک قافلہ سے پیش آیا تھا اور جب وہ قافلہ مکہ میں پہنچا تو اس نے تسلیم کیا کہ بات درست ہے(در منثور زیر آیت سبحان الذی اسـرٰی).اب یہ ایک زائد فائدہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا نظارہ دکھانے سے حاصل ہوا کہ لوگوں کے ایمان بڑھ گئے اور کفار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ آپؐنعوذ باللہ افتراء سے کام لیتے ہیں ان کا منہ بند ہوگیا.غرض اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے اہم کلام کے اظہار کے لئے تصویری زبان کو بھی استعمال کرلیتا ہے یعنی تمثیلی زبان میں بھی ایک واقعہ بیان کردیتا ہے اور پھر لفظی وحی میں بھی اس کا ذکر کردیتا ہے لیکن بہرحال دائمی کلام لفظی ہی ہوتا ہے تصویری کلام نہیں ہوتا.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایک الہام بھی اسی قسم کا ہے جس میں دونوں صورتیں اختیار کی گئی ہیں تصویری زبان بھی اور لفظی الہام بھی.آپ کا الہام ہے جَاءَنِیْ اٰیِلٌ وَاخْتَارَ وَاَدَارَ اِصْبَعَہٗ وَاَشَارَ اِنَّ وَعْدَاللہِ اَتٰی فَطُوْبٰی لِمَنْ وَّجَدَ وَرَاٰی(تذکرہ صفحہ ۵۵۹ ) میرے پاس جبریل آیا اور اس نے مجھے چن لیا.اس نے اپنی انگلی کو گرد ش دی اور اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آگیا ہے پس مبارک وہ جو اس کو پائے اور دیکھے.اب دیکھو یہ ایک نظارہ تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دکھایا گیا کہ جبریل آپ کے پاس آیا اس نے اپنی انگلی کو گردش دی اور اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آگیا ہے.مگر اللہ تعالیٰ پھر اس واقعہ کو کلام کی صورت میں بھی لے آیا تاکہ اور لوگ بھی اس سے متاثر ہوں.یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے ایک بڑا اونچا پہاڑ دیکھا ہے تو جو اثر اس کا دیکھنے والے پر ہوتا ہے وہ سننے والے پر نہیں ہوتا.اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی واقعہ کو نظارہ کی صورت میں لاکر اس کے اثر کو زیادہ گہرا کرنا چاہتا ہے مگر پھر الہام میں بھی اسے بیان کردیتا ہے تاکہ دوسروں پر بھی اثر ہو.مثلاً جبریل نے اپنی انگلی سے جو اشارہ کیا ہوگا اس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو اثر ہوا ہوگا وہ اثر خالی لفظوں سے نہیں ہوسکتاتھا.لیکن اس کے مقابلہ میں دوسرے لوگوں پر صرف خواب کا ذکر کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوسکتا تھا ان کے لئے ضروری تھا کہ لفظی الہام
Page 79
نازل کیا جاتا.یہی حکمت ہے جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ اپنے اہم کلام کو بعض دفعہ دونوں صورتوں میں بیان کردیتا ہے تصویری زبان میں بھی اور لفظی الہام میں بھی.اس بحث کے بعد اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو تین اقسام وحی کی بیان کی ہیں ان کی آگے تجربہ کی بناء پر اور بھی کئی قسمیں ہیں جو یہ ہیں: وحی کی تئیس اقسام پہلی قسم (۱) خواب تعبیر طلب منفرد و مشترک.مثلاً ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ فلاں شخص کے مکان کی دیوار گرگئی ہے.اب ضروری نہیں کہ اس کے مکان کی دیوار ہی گرے بلکہ اس کے معنے یہ ہوں گے کہ جو اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے یا اس کو مشکلات و حوادث سے بچانے والے ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے یا ان پر وبال آجائے گا.یہ خواب کبھی منفرد ہوتی ہے یعنی صرف ایک شخص ہی دیکھتا ہے اور کبھی مشترک ہوتی ہے یعنی ایسی ہی خواب دوسر ے کو بھی آجاتی ہے.دراصل غیر نبی کا کلام چونکہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ طریق رکھا ہوا ہے کہ بعض دفعہ بعینہٖ ویسا ہی رؤیا دوسرے کو بھی دکھا دیا جاتا ہے.ہم نے اپنی زندگی میں اس کا کئی دفعہ تجربہ کیا ہے کہ بعض دفعہ جس قسم کی خواب آتی ہے بعینہٖ اسی قسم کی خواب دوسرے کو آجاتی ہے.میں نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں ایک رؤیا کا ذکر کیا جو ۲۴؍مئی ۱۹۴۴ء کے الفضل میں شائع ہوچکا ہے اس کے بعد ایک دوست نے بتایا کہ مجھے ایک غیراحمدی دوست نے اپنا ایک رؤیا سنایا تھا اور بتایا تھا کہ اسے خواب میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ رؤیا خلیفۃ المسیح کو بھی دکھایا گیا ہے.چنانچہ میں ’’الفضل‘‘ میں آپ کا رؤیا پڑھ کر حیران رہ گیا کہ ایسا ہی رؤیا اس غیراحمدی دوست نے دیکھا تھا (الفضل مورخہ ۲۷؍مئی ۱۹۴۴ء) پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظارے تو مختلف دکھائے جاتے ہیں مگر ان کی تعبیر ایک ہی ہوتی ہے.ابھی تھوڑے دن ہوئے روس کے متعلق میں نے ایک رؤیا دیکھا جو الفضل یکم ستمبر ۱۹۴۵ء میں شائع ہوچکا ہے.میں نے جس تاریخ کو یہ خواب دیکھا ہے اس کے دوسرے دن ہی میاں روشن دین صاحب زرگر کا مجھے ایک خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے روس کے متعلق یہ رؤیا دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی وہی تھی جومیرے رؤیا کی تھی.اب دیکھو مجھے ان کی خواب کا علم نہیں انہیں میری خواب کا علم نہیں.میں الفضل والوں کو خواب لکھتا ہوں اور میاں روشن دین مجھے لکھتے ہیں اور دونوں کی تعبیر ایک ہی ہوتی ہے.غرض اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندے کو یہ یقین دلانے کے لئے کہ تمہاری خواب بالکل سچی ہے ویسی ہی خواب دوسرے کو بھی دکھادیتا ہے.بعض دفعہ تو دونوں کا ایک جیسا نظارہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ نظارہ تو جدا جدا ہوتا ہے مگر تعبیر ایک ہوتی ہے.غرض پہلی قسم یہ ہے کہ انسان ایسا رؤیا دیکھتا ہے جو تعبیر طلب ہوتا ہے یہ خواب منفرد بھی ہوتی ہے اور مشترک بھی.یعنی کبھی صرف خود ایک نظارہ دیکھتا ہے اور کبھی ویسا ہی نظارہ دوسروں کو بھی دکھادیا جاتا ہے.
Page 80
دوسری قسم(۲) خواب مثل فلق الصبح منفرد ومشترک.کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان رؤیا میں دیکھتا ہے کہ دیوار گرگئی اور دوسرے دن واقعہ میں ایسا ہی ہوتا ہے.بارش برستی ہے اور مکان کی دیوار گر جاتی ہے.یہ خواب بھی کبھی تو منفرد ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کو بھی ویسی ہی خواب آجاتی ہے اور جو کچھ دیکھا جاتا ہے ویسا ہی ظہور میں آجاتا ہے.یہ نہیں ہوتا کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو بلکہ جس رنگ میں خواب کے ذریعہ کوئی بات بتائی جاتی ہے اسی رنگ اور اسی شکل میں فلق الصبح کی طرح وہ بات پوری ہوجاتی ہے.اس قسم کی خوابوں کا بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت تجربہ ہے اور میں نے دیکھا ہے بسا اوقات جس طرح رات کو ایک نظارہ دیکھا جاتا ہے ویسا ہی دن کو ہونے لگ جاتا ہے.اور چونکہ اس قسم کے واقعات بڑی کثرت سے ہوئے ہیں اس لئے بعض دفعہ تو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ واقعہ دوبارہ تو نہیں ہو رہا.یہ خواب بھی بعض دفعہ منفرد ہوتی ہے اور بعض دفعہ مشترک.یعنی کبھی تو اس قسم کی خواب دیکھنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا لیکن کبھی ویسا ہی نظارہ دوسرے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں.تیسری قسم (۳) نظارہ نیم خواب تعبیر طلب منفرد و مشترک.بعض دفعہ انسان پورے طور پر سویا ہوا نہیں ہوتا بلکہ نیم خواب کی سی حالت اس پر طاری ہوتی ہے.کچھ جاگ رہا ہوتا ہے اور کچھ غنودگی کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے کہ اس حالت نیم خوابی میں وہ ایک نظارہ دیکھتا ہے جو تعبیر طلب ہوتا ہے.یہ نظارہ بھی دونوں قسم کا ہوتا ہے یعنی منفرد بھی ہوتا ہے اور مشترک بھی.چوتھی قسم (۴) نظارہ نیم خواب مثل فلق الصبح منفرد و مشترک.انسان بعض دفعہ نیم خوابی کی حالت میں ایک نظارہ دیکھتا ہے مگر وہ تعبیر طلب نہیں ہوتا بلکہ بعینہٖ اسی رنگ میں پور اہوجاتا ہے جس رنگ میں اس نے نظارہ دیکھا ہوتا ہے.یہ نظارہ بھی منفرد اور مشترک دونوں قسم کا ہوتا ہے.پانچویں قسم (۵) نظارہ بیداری تعبیر طلب منفرد و مشترک.بعض دفعہ بیداری میں ایک نظارہ دیکھا جاتا ہے لیکن وہ ہوتا تعبیر طلب ہے.ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے فلاں دن آپؑکو فلاں اسٹیشن پر دیکھا تھا کیا آپ وہاں تشریف لے گئے تھے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو وہاں نہیں گئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کشفی طور پر ہمیں دیکھا ہوگا.تو بعض دفعہ عین بیداری کی حالت میں ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے مگر وہ ہوتا تعبیر طلب ہے.یہ نظارہ بھی منفرد اور مشترک دونوں قسم کا ہوتا ہے.
Page 81
وحی کی چھٹی قسم (۶) نظارئہ بیداری مثل فلق الصبح منفرد و مشترک.کبھی بیداری میں ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے مگر وہ تعبیر طلب نہیں ہوتا بلکہ فلق الصبح کی طرح اسی رنگ میں ظاہر ہوجاتا ہے جس رنگ میں اللہ تعالیٰ انسان کو نظارہ دکھاتاہے.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کشوف میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں.ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کشفی حالت میں دیکھا کہ مبارک احمد چٹائی کے پاس گر پڑا ہے اور اسے سخت چوٹ آئی ہے.ابھی اس کشف پر تین منٹ سے زیادہ عرصہ نہیں گذرا ہوگا کہ مبارک احمد جو چٹائی کے پاس کھڑا تھا اس کا پیر پھسل گیا اسے سخت چوٹ آئی اور اس کے کپڑے خون سے بھر گئے (تذکرہ صفحہ ۳۳۶ ).اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مجھے ایک دفعہ پیچش کی شکایت تھی اور چونکہ مجھے بار بار قضائے حاجت کے لئے جانا پڑتا تھا اس لئے میں چاہتا تھا کہ پاخانہ کی اچھی طرح صفائی ہوجائے تاکہ طبیعت میں انقباض پیدا نہ ہو.خاکروبہ آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جگہ صاف کردی ہے اس وقت شاید اس نے جھوٹ بولا یا کوئی کونہ صاف کرنا اسے بھول گیا تھا کہ اس نے جواب میں کہا میں نے جگہ صاف کردی ہے.اسی وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کشفی حالت طاری ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ایک کونہ میں نجاست پڑی ہے.اس پر آپ نے اسے کہا تم جھوٹ کیوں بولتی ہو فلاں کونہ تو ابھی گندا ہے اور تم نے اس کی صفائی نہیں کی.وہ یہ سن کر حیران رہ گئی کہ انہیں اندر بیٹھے کس طرح علم ہوگیاہے کہ میں نے پوری صفائی نہیں کی ( تذکرہ صفحہ ۳۶۸ ).یہ نظارہ بھی منفرد اور مشترک دونوں رنگ رکھتا ہے یعنی کبھی صرف ایک شخص کو نظارہ دکھایا جاتا ہے اور کبھی ویسا ہی نظارہ دوسروں کو بھی دکھا دیا جاتا ہے.وحی کی ساتویںقسم (۷) کلام بلاواسطہ جو کانوں پر گرتاہے منفرد و مشترک.بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ کی صورت میں انسانی کانوں پر نازل ہوتا ہے اور غیب سے آواز آتی ہے کہ یوں ہوگیا ہے یا یوں ہوجائے گا یا یوں کر.گویا ماضی کے صیغہ میں بھی یہ کلام نازل ہوتا ہے، مستقبل کے صیغہ میں بھی نازل ہوتا ہے اور امر کی صورت میں بھی نازل ہوتا ہے.یہ بلاواسطہ کلام جس کی کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے اس کی بھی دونوں حیثیتیں ہیں یعنی یہ منفرد بھی ہوتا ہے اور مشترک بھی.کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف ملہم کو ایک آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی ویسی ہی آواز دوسرے کو بھی آجاتی ہے.اس قسم کا مجھے ذاتی طور پر تجربہ حاصل ہے.ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہام ہوا کہ اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ بَغْتَۃً.میں اپنی افواج کے ساتھ اچانک تیری مدد کے لئے آئوں گا.جس رات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا اسی رات ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ
Page 82
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آج یہ الہام ہوا ہے کہ اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ بَغْتَۃً.جب صبح ہوئی تو مفتی محمد صادق صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو تازہ الہامات ہوئے ہوں وہ اندر سے لکھوالائو.مفتی صاحب نے اس ڈیوٹی پر مجھے مقرر کیا ہوا تھا اور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تازہ الہامات آپ سے لکھوا کر مفتی صاحب کو لاکر دے دیا کرتا تھا تاکہ وہ انہیں اخبار میں شائع کردیں.اس روز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب الہامات لکھ کر دیئے تو جلدی میں آپ یہ الہام لکھنا بھول گئے کہ اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ بَغْتَۃً.میں نے جب ان الہامات کو پڑھا تو میں شرم کی وجہ سے یہ جرأت بھی نہ کرسکتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس بارہ میں کچھ عرض کروں اور یہ بھی جی نہ مانتا تھا کہ جو مجھے بتایا گیا تھا اسے غلط سمجھ لوں.اسی حالت میں کئی دفعہ میں آپ سے عرض کرنے کے لئے دروازہ کے پاس جاتا مگر پھر لوٹ آتا.پھر جاتا اور پھر لوٹ آتا.آخر میں نے جرأت سے کام لے کر کہہ ہی دیا کہ رات مجھے ایک فرشتہ نے بتایا تھا کہ آپ کو الہام ہوا ہے اِنِّیْ مَعَ الْاَفْوَاجِ اٰتِیْکَ بَغْتَۃً مگر ان الہامات میں اس کا ذکر نہیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا یہ الہام ہوا تھا مگر لکھتے ہوئے میں بھول گیا.چنانچہ کاپی کھولی تو اس میں وہ الہام بھی درج تھا.چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھر اس الہام کو بھی اخبار کی اشاعت کے لئے درج فرما دیا.اب یہ ایک بلا واسطہ کلام تھا جو آپ کے کانوں پر نازل ہوا مگر ساتھ ہی مجھے بھی بتادیا گیا کہ آپ کو یہ الہام ہوا ہے.وحی کی آٹھویں قسم (۸) کلام بلا واسطہ جو قلب پر گرتا ہے منفرد و مشترک.یہ قسم ایسی ہے جو پہلی قسم سے علیحدہ ہے.پہلی قسم میں تو کان پرکلام نازل ہوتا ہے مگر اس قسم میں انسانی قلب پر کلام نازل ہوتا ہے.کان کی حس چونکہ معروف ہے اس لئے اسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے مگر اس حس کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے.لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ وہ بعض دفعہ انسانی قلب کو اپنی وحی کا مہبط بنادیتا ہے.انسان یہ محسوس نہیں کرتا کہ اس کے کان پر الفاظ نازل ہوئے ہیں بلکہ وہ اپنے قلب پر ان الفاظ کا ’’نزول‘‘ محسوس کرتا ہے (یہ بات خیال سے بالکل جداگانہ ہے).یہ کلام بھی منفرد اور مشترک دونوں قسم کا ہوتا ہے.وحی کی نویں قسم (۹) کلام بلا واسطہ جو زبان پر نازل ہوتاہے منفرد ومشترک.یعنی الہام کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کان کوئی آواز نہیں سن رہے ہوتے لیکن زبان پر بے تحاشا ایک فقرہ جاری ہوتا ہے جسے بار بار وہ دہراتی چلی جاتی ہے.اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبان کسی اور کے قبضہ میں ہے اور وہ جلدی جلدی ایک فقرہ بولتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ربودگی کی کیفیت جو انسان پرطاری ہوتی ہے جاتی رہتی
Page 83
ہے مگر اس کے بعد بھی کچھ دیر تک زبان پر یہ تصرف جاری رہتا ہے اور وہ جلدی جلدی اس فقرہ کو دہراتی رہتی ہے تاکہ انسان کو اچھی طرح یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرکیا الہام نازل کیا ہے.ایسے الہام میں بھی کبھی بطور گواہی دوسروں کو شریک کردیا جاتا ہے.وحی کی دسویں قسم (۱۰) کلام بلا واسطہ جو آنکھوں پر نازل ہوتا ہے منفرد و مشترک.کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آنکھوں پر نازل ہوتا ہے یعنی لکھے ہوئے الفاظ پیش کئے جاتے ہیں جن کو پڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ کے منشا سے آگاہ ہوجاتا ہے.یہ کلام بھی دونوں رنگ میں ہوتا ہے یعنی منفرد طور پر بھی اور مشترک طور پر بھی.کبھی تو صرف اسے کوئی لکھی ہوئی چیز نظر آجاتی ہے اور کبھی دوسرے لوگ بھی اس نظارہ میں شریک کردیئے جاتے ہیں.یہ امر بتایا جاچکا ہے کہ لغت کے لحاظ سے وحی کے ایک معنے تحریر کے بھی ہیں.یہ معنے اس دسویں قسم میں آجاتے ہیں کیونکہ اس میں الفاظ تحریرکی صورت میں دکھائے جاتے ہیں اور درحقیقت وحی کی قطعیت الفاظ کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہے.کان، آنکھ، زبان یا دل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی.جو وحی الفاظ کی صورت میں نازل ہو وہ بہرحال اور تمام وحیوں سے زیادہ شاندار سمجھی جائے گی اور اس کی قطعیت میں کوئی شبہ نہیں ہوگا خواہ یہ قطعیت کان سے حاصل ہو خواہ دل سے حاصل ہو خواہ زبان سے حاصل ہو خواہ آنکھ سے حاصل ہو.جس وحی کے متعلق انسان قسم کھاکر کہہ سکتا ہو کہ اس کا لفظ لفظ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے.اس کی زبر اس کی زیر اس کا لام اور اس کامیم سب خدا نے نازل کیا ہے وہ وحی کی تما م قسموں میں سے زیادہ اعلیٰ سمجھی جائے گی.گیارھویںقسم (۱۱) کلام بلا واسطہ جو کانوں پر گرتا ہے اور زبان بھی شریک کردی جاتی ہے.یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے صرف کانوں پر نازل نہیں ہوتا بلکہ زبان بھی اس کو دہراتی چلی جاتی ہے اور جب ربودیت کی حالت جاتی رہتی ہے تو کان محسوس کررہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ کا کلام سنا اورساتھ ہی زبان بھی گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا.بارھویں قسم (۱۲) کلام بلا واسطہ جو آنکھوں پر گرتا ہے اور زبان بھی اس میں شریک کردی جاتی ہے.یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تختی دکھائی جاتی ہے جس پر الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر ساتھ ہی زبان بھی ان الفاظ کو دہراتی چلی جاتی ہے.تیرھویں قسم (۱۳) کلام بلا واسطہ جو قلب پر گرتاہے اور زبان بھی اس میں شریک کردی جاتی ہے.چودھویں قسم (۱۴) کلام بلا واسطہ جس میں دونوں حواس ظاہری اور تیسرا باطنی بھی شریک کردیئے جاتے
Page 84
ہیں.یعنی کبھی اتنے جلال سے خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے کہ ادھر وہ قلب پر گررہا ہوتا ہے ادھر کانوں پر نازل ہورہا ہوتا ہے اور پھر تیسری طرف زبان بھی اس کو دہراتی چلی جاتی ہے.(۱۵) کلام بالواسطہ جو نظر آنے والے فرشتہ کے ذریعہ سنایا جاتا ہے اس کلام میںواسطہ پیدا کر دیا جاتا ہے.بجائے اس کے کہ انسان براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے اسے فرشتہ نظر آتا ہے جو کہتا ہے کہ بات یوں ہے جیسے غار حرا میںہوا.(۱۶) کلام بالواسطہ جو نظر آنے والے فرشتہ کے ذریعہ دکھایا جاتا ہے جیسے بعض حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ غار حرا میں جبریل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حریر پر لکھی ہوئی ایک تحریر بھی دکھائی(درمنثور سورۃ العلق زیر آیت اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ) (۱۷) کلام بالواسطہ جو نہ نظر آنے والے فرشتہ کے ذریعہ سنایا جا تا ہے اس میں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا مگر آواز سنائی دیتی ہے کہ میں ایسا کہتا ہوں یا فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے یہ بات پہنچانے کا حکم دیا ہے.(۱۸) کلام بالواسطہ جو نہ نظر آنے والے فرشتہ کے ذریعہ دکھایا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے تختی آتی ہے جس پر کچھ لکھا ہو ا ہوتا ہے اور صاف پتہ لگتاہے کہ کسی اور ہاتھ نے اس کو آگے کر دیا ہے مگر فرشتہ نظر نہیں آتا.(۱۹) کلام بالواسطہ جو نظر آنے والے فرشتہ کے ذریعہ سے یقظہ میں سنایا جاتا ہے اور دوسرے اس میں شریک نہیں ہوتے یعنی انسان کے حواس ظاہری پور ا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے فرشتہ نظرآتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سناتا ہے مگر کوئی دوسراشخص اس میں شریک نہیں ہوتا نہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے اور نہ اس کی آواز سن سکتا ہے.(۲۰) کلام بالواسطہ جو نظر آنے والے فرشتہ کے ذریعہ سنایا جاتا ہے.اور دوسرے اس میں سماعاً شریک ہوتے ہیں رؤیۃً نہیں.بخاری میںآتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے باتیں کرتے سنا.حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپؐکس سے باتیں کر رہے ہیں.آپؐنے فرمایا جبریل آیا ہے جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور وہ تمہیںالسلام علیکم کہتا ہے.(بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب فضل عائشہ رضی اللہ عنہا) اب دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے با تیں سن لیں مگر انہیں فرشتہ نظر نہ آیا.پس یہ وہ قسم ہے جس میں اور لوگ سماعاً تو شریک کردیئے جاتے ہیں مگر رؤیۃً نہیں.(۲۱) کلام بالواسطہ جو نظر آنے والے فرشتے کے ذریعہ سے سنایا جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس میں سماعاً و رؤیۃً شریک ہوتے ہیں جیسے دحیہ کلبی کی شکل میںجبریل کے آنے کا واقعہ ہے.وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں
Page 85
آئے آپ ؐسے باتیں کرتے رہے اور صحابہ نے ان کو اچھی طرح دیکھا.جب وہ چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَالِکَ جِبْـرِیْلُ وہ جبریل تھے جو تمہیں دین کی باتیں سکھانے آئے.ا س کلام کو صحابہ ؓ نے بھی سنا اور فرشتہ کو بھی دیکھا.(مسلم کتاب الایـمان باب الایمان ماھو وَ بیان خصالہٖ) (۲۲) خواب، کلام اور حقیقت ظاہر تینوں کا اشتراک بعض دفعہ ایک نظارہ میں تینوں صورتیںجمع کر دی جاتی ہیں.اس میں خواب بھی ہوتی ہے، اس میںکلام بھی ہوتا ہے اور اس میں حقیقت ظاہر بھی ہوتی ہے.جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سرخی کے چھینٹوں والا واقعہ پیش آیا جس کے نشانات آپ کے کرتہ پر بھی پائے گئے.اس میں تینوں باتیں موجود تھیں.یعنی خواب میں ایک نظارہ بھی دکھایا گیا.اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات بھی کی اور پھر ظاہر میں سرخی کے چھینٹوں کا نشان قائم کر دیا.پس وحی کی بائیسویں قسم وہ ہے جس میںخواب، کلام اور حقیقت ظاہر تینوں کا اشتراک پایا جاتا ہے.(۲۳) وحی کی تیئیسویں قسم وحی قلبی خفی ہے یعنی وہ وحی جس میںالفاظ نہیں ہوتے صرف دل پر اللہ تعالیٰ کے منشا کا القاء ہوتا ہے.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ روح القدس کی طرف سے فلاں بات میرے دل میںڈال دی گئی ہے اور اب مجھے اس میں کسی قسم کا تردد نہیں.یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی الفاظ کی شکل میں نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ صرف قلبی وحی تھی جو القاء کی صورت میں نازل ہوئی.وحی کا مفہوم سمجھنے سے بہائیوں کو دھوکہ اس وحی کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وحی دوسری وحیوں کے ساتھ مل کر آتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی دوسری وحیوں کے بعد آتی ہے تا کہ لوگوں کو کسی قسم کا دھوکہ نہ لگے.بہائیوں کو تمام تر دھوکہ اسی آخری تیئیسویں وحی کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لگا ہے ہم اس وحی سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا اپنا تجربہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کی وحی ہوتی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی ایک قسم قلبی خفی وحی بھی ہے.پس ہم یہ تو نہیںکہہ سکتے کہ بہائی جس وحی کا ادّعا کرتے ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں.مگر ہم یہ ضرور کہیںگے کہ بہائیوں نے اس وحی کی حقیقت کو نہیںسمجھا.وہ اپنے دل کے ہر خیال کا نام وحی رکھنے کے عادی ہیں.چنانچہ بہاء اللہ کے دل میں جو خیال آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ وحی ہے.اسی طرح وہ جو کچھ لکھتے ہیںاس کو وحی قلبی خفی قرار دے دیتے ہیں.ہمیںچونکہ خود اعتراف ہے کہ وحی کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جس میں الفاظ نازل نہیں ہوتے صرف قلب
Page 86
میںاللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کیا جاتا ہے اس لئے وہ بعض دفعہ لوگوں کو دھوکہ دینے میںکامیاب ہو جاتے ہیں.بہائیوں کے ساتھ بحث کرنے میں ایک حربہ مگر ایک بات ایسی ہے جو اس بحث کے سلسلہ میں ہماری جماعت کے دوستوں کو یاد رکھنی چاہیے اور جو بہائیوں کے پھیلائے ہوئے زہر کے ازالہ میںبہت کام آسکتی ہے اور وہ یہ کہ مامورین کے تجربہ میں یہ بات آئی ہے کہ یہ وحی دوسری وحیوں کے ساتھ مل کر آتی ہے اکیلی نہیںآتی.اگر اکیلی آجائے توہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی وحی ہوتی ہے اور پھر یہ امتیاز کرنا مشکل ہو جائے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ سے کام لے رہا ہے اس نقص کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت رکھی ہے کہ وہ پہلے اپنے بندہ پر اور قسموں کی وحی نازل کرتا ہے اور جب اس میں بیان کردہ واقعات کے پورا ہونے سے لوگوں کو یہ یقین آجاتا ہے کہ فلاں شخص سچ بول رہا ہے تو اس کے بعد اس پر وحی قلبی خفی بھی نازل کر دیتا ہے.یہ نہیں ہوتا کہ اسے اپنی سچائی کا اور تو کوئی نشان نہ دیا جائے اور صرف قلبی خفی وحی اس کی طرف نازل کرنی شروع کر دی جائے.اور یہ لفظی وحی کے مقابلہ پر کمیت میںبہت ہی کم ہوتی ہے.وحی خفی کی پہچان میںاس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں.میرے پاس ایک دفعہ عبدا للہ تیما پوری آئے اور کہنے لگے آپ مجھے کیوں نہیں مانتے اور مرزا صاحب کو کیوں مانتے ہیں.میں نے کہا مرز ا صاحب کو ہم اس لئے مانتے ہیںکہ آپ کی صداقت کے ہم نے متواتر نشانات دیکھے اور ہمیں یقین آگیا کہ آپ سچے ہیں.کہنے لگے یہ تو بعد کی باتیں ہیں شروع شروع میںجو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے انہوں نے کون سا نشان دیکھا تھا؟ مثلاً حضرت مولوی نورالدین صاحبؓآپ پر ایمان لائے سوال یہ ہے کہ وہ کس نشان کو دیکھ کر آپ کی صداقت کے قائل ہوگئے تھے ؟ میں نے کہا دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ابو بکر ؓ کی طرح نشانات دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نشانا ت دیکھ کر ایمان لائے تو اس سے ہمارا درجہ کم ہو جائے گا.چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیثوں میںصاف طور پر آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی ان کو خبر پہنچی اور وہ آپ سے یہ دریافت کرنے آئے کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے الہام کا دعویٰ کیا ہے تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی صداقت کے متعلق کچھ وضاحت فرمائیں مگر حضرت ابو بکر ؓ نے آپ کو روک دیا اور کہاآپ صرف اتنا بتائیںکہ کیا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور پھر کہا میں نے اس لئے دلائل سننے سے انکار کیا تھا کہ اگر میں دلائل سن کر ایمان لاتا تو میں اپنے ایمان کے کمزور ہونے کا
Page 87
ثبوت مہیا کرنے والا ہوتا.میںنہیں چاہتا تھا کہ میرے ایمان کی بنیاد نئے دلائل اور نشانات پر ہو.بلکہ میںچاہتا تھا کہ میں جو مشاہدہ آپ کے اخلاق کا کر چکا ہوں اسی کی بناء پر آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کروں.یہی حال حضرت خلیفۂ اوّلؓ کا تھا.عبداللہ تیما پوری کہنے لگے تو پھر میرے متعلق آپ یہ کیوں شرط قائم کرتے ہیں کہ میرے لئے نشان دکھا نا ضروری ہے.میں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ نبی کے دعویٰ کی ابتدا میں ایمان لانے والے ان زبردست نشانات کے ظہور سے پہلے ایمان لاتے ہیںجو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں.لیکن ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی یقینی صورتیں پیدا کر دیتا ہے.اور وہ اس نبی کا گذشتہ نمونہ اور عمل ہوتا ہے مگر اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس کے ذاتی واقف ہوں.حضرت ابوبکر ؓ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت امانت اور بنی نوع انسان کی خدمت تھی، حضرت خلیفہ اوّل کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق باللہ، اسلام کے احیاء کا جوش اور اس کے لئے غیر معمولی علمی خدمت تھی جس کی وجہ سے آپ نے براہین احمدیہ جیسی معجزانہ کتاب لکھی.ابتدائی زمانہ کے راستباز لوگ دیکھ رہے تھے کہ آپ نے براہین احمدیہ کے نام سے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں صداقت اسلام کے ایسے زبر دست دلائل دیئے اور اس طرح تحدی سے دشمنان دین کو مقابلہ کے لئے للکارا ہے کہ یہ کام بغیر تائید الٰہی کے نہیں ہو سکتا.اس لئے نیک لوگ جن کے دل صاف تھے فوراً پکار اٹھے کہ یہ شخص اسلام کا پہلوان اور دین کو دشمنوں کے نرغے سے محفوظ رکھنے والا ہے.اس کے بعد جب آپ نے دعویٰ کیا تو جو لوگ آپ کے حالات سے واقف تھے وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے وہ نور بخشا تھا جس کی بنا ء پر اس نے براہین احمدیہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھی وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا.جس نے اسلام کی پہلے حفاظت کی ہے وہ اگر اب بھی اس کی حفاظت کا دعویٰ کرتا ہے تو بالکل سچ کہتا ہے، چنانچہ لوگوں نے براہین کا نشان دیکھنے کے بعد کسی مزید نشان دیکھنے کی ضرورت نہ سمجھی اور آپ کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گئے.عبداللہ تیماپوری کہنے لگے تو پھر میرے متعلق آپ کیا نشان چاہتے ہیں ؟ میں نے کہا براہین احمدیہ نا مکمل رہ گئی ہے اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لئے نامکمل رہنے دیا ہے کہ کوئی آنے والا اس کو مکمل کرے.اب آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور بنایا ہے آپ اس کو مکمل کر دیں تو میںآپ کو آپ کے دعویٰ میں صادق تسلیم کر لوں گا اور سمجھ لوں گا کہ آپ کی صداقت کے لئے یہ نشان کافی ہے.اس پر وہ اچھا کہہ کر چلے گئے مگر آج تک ایک سطر بھی براہین احمدیہ کی تکمیل کے لئے نہیں لکھ سکے.جس طرح مامورین کی بعثت والی زندگی سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے شواہد پیدا کر دیتا ہے جو لوگوں کے لئے ایمان
Page 88
کے محرک ہوتے ہیں.اسی طرح وحی قلبی خفی کے نازل ہونے کا ادّعا کرنے والے انسان کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پر دوسری وحی بھی نازل ہوتی ہو اور اس کی صداقت کے ایسے دلائل اور شواہد پائے جاتے ہوں جن کی بنا ء پر کسی شخص کے دل میںاس کے وہمی یا پاگل ہونے کا خیال نہ گذرے.مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ روح القدس نے فلاں بات میرے دل میںڈال دی ہے تو صحابہ کو اس کے ماننے میں کوئی تامل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلق الصبح کی طرح پوری ہونے والی وحی بھی نازل ہو چکی تھی.جبریل کے ذریعہ بھیجی جانے والی وحی بھی نازل ہو چکی تھی اور وہ کلام بھی آپ پر نازل ہو چکا تھا جو مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ ہوتا ہے.اور وہ سمجھ سکتے تھے کہ جس شخص نے ہمیشہ سچی باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیںوہ اب بھی جو کچھ کہہ رہا ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتا.حدیثوں میںآتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہاآپ نے میرا اتنا قرض دینا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میںتو تمہاری رقم واپس کر چکا ہوں اس نے کہا آپ واپس دے چکے ہیں تو کوئی گواہ پیش کریں.اس پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میںاللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کے روپے ادا کر دیئے ہیں.یہودی نے یہ بات سنی تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں مجھے یاد آگیا آپ نے مجھے روپے دے دیئے تھے.جب وہ واپس چلا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تمہیں کس طرح پتہ ہے کہ میں نے یہ روپے ادا کر دیئے تھے جب میں نے یہ قرض واپس کیا ہے اس وقت تو تم موجود نہیں تھے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جانے بھی دیجئے آپ آسمان کی باتیں ہمیںبتاتے ہیںتو ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں کیا زمین کی بات آپ کہیں گے تو ہم اس پر ایمان نہیںلائیں گے.جس طرح ہم آپ کی آسمان والی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو زمین سے تعلق رکھنے والی باتوں میں بھی سچا اور راستباز سمجھتے ہیں یہ بات جو اس صحابی ؓ نے بیان کی بالکل درست ہے.کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کا مامور اور مرسل ہے اگر وہ کوئی بات کہے گا تو بہر حال سچ ہی ہو گی.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بات کہے.چنانچہ جب اس صحابی نے یہ بات کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملامت نہیںکی بلکہ آپ خوش ہوئے اور فرمایا آئندہ اس شخص کی گواہی دو گواہوں کے برابر سمجھی جائے.یہ فضیلت اسے دوسروں پر اسی لئے عطا کی گئی کہ اس نے محض دوستی کی خاطر بات نہیں کی بلکہ اپنی گواہی کی بنیاد اس نے کلام الٰہی پر رکھی اور کہا کہ جس شخص پر خدا تعالیٰ روزانہ اپنا کلام نازل کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اس کی دوسری بات بھی جو زمین سے تعلق رکھنے والی ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتی.اسی طرح جس شخص پر اللہ تعالیٰ وحی قلبی خفی نازل کرتا ہے اسے دوسرے شواہد بھی
Page 89
عطا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کوئی دھوکا نہ لگے اور وہ سمجھ لیں کہ جو شخص پہلی وحی کے بیان کرنے میںراستبازی سے کام لے رہا ہے وہ اس وحی میں بھی ضرور صادق اور راستباز ہے.لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نہ اس پر کثرت سے وحی لفظی نازل ہوتی ہے نہ اس پروحی جبریلی نازل ہوتی ہے نہ اس پر تصویری یا تعبیری زبان میں وحی نازل ہوتی ہے اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ مجھے وحی قلبی خفی ہوتی ہے تو اس کا یہ دعویٰ کسی عقلمند کی نگاہ میںقابل قبول نہیںہو سکتا.ہر شخص کہے گا کہ وہ پاگل ہے جو اپنے دل کے خیالات کا نام وحی رکھ رہا ہے.غرض یہ وحی بڑا فتنہ پیدا کرنے والی چیز ہے.یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وحی کو کلام لفظی اور جبریلی اور غیر جبریلی وحی کے تابع رکھتا ہے.جس شخص پر بکثرت یہ تین وحیاں نازل ہوں وہ اگر کہے کہ مجھ پر وحی قلبی خفی نازل ہوتی ہے توہم اسے فریب خوردہ نہیںکہیں گے اور اس کی بات مان لیں گے.لیکن جب کوئی دوسرا شخص یہ کہے جس پر کوئی اور وحی نازل نہ ہوتی ہو تو ہم سمجھیں گے وہ پاگل ہے.یہی حال بہاء اللہ اور لاہور کے غلا م محمد کا ہے ہم ان لوگوں کو بھی عام معیار عقل سے گرا ہوا خیال کرتے ہیں.دوسرے یہ وحی امور غیبیہ کے متعلق ہوتی ہے امور احکامیہ کے بارہ میں نہیںتا کہ دھوکا نہ لگے.کیونکہ امور غیبیہ میںفتنہ کا اندیشہ نہیںہوتا ان کی تفسیر بعد میںہو جاتی ہے مگر امور احکامیہ کے نزول کی کوئی تفسیر بعد میں نہیں ہوتی.کلامِ الٰہی کےسمجھنے کا ایک گُر کلام الٰہی کے متعلق یہ با ت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سب اقسام کلام حقیقت ظاہر اور مجاز دونوں قسم کی عبارتوں پر مشتمل ہوتے ہیں.یہ ضروری نہیں کہ اس میںصرف حقیقت ظاہری پائی جاتی ہو.بلکہ جس طرح منام میں دیکھی گئی چیز تعبیر طلب ہوتی ہے اسی طرح وہ کلام بھی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر نازل فرماتا ہے اس میں مجاز اور استعارات پائے جاتے ہیں.فرق صرف یہ ہے کہ منام میںجو نظارہ دکھایا جائے وہ اکثر تعبیر طلب ہوتا ہے لیکن الفاظ کی صورت میں جو کلام نازل ہوتا ہے اس میںسے بعض تاویل طلب ہوتا ہے اس نکتہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جب غیر احمدیوں کے سامنے ہم قرآن کریم کی آیات کے وہ مطالب بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میںمخفی رکھے ہوئے ہیں تو وہ کہہ دیا کرتے ہیںتم تو کلام الٰہی کی تاویل کرتے ہو.بجائے ا س کے کہ ظاہرالفاظ جس حقیقت کی طرف راہنمائی کرتے ہیں تم اس کو لو ان الفاظ کی تاویل کرنا شروع کر دیتے ہو.ان کے ذہن میں یہ بات مرکوز ہوتی ہے کہ کلام الٰہی کی تاویل نہیں کی جا سکتی بلکہ ہمیشہ اس کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اور اگر تاویل کی جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کلام الٰہی کی بھی تاویل کی جائے تو پھر تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا.یہ ایسی عقل کے خلاف بات ہے کہ اسے سن کر حیرت آتی ہے.آخر دنیا میںعام بول چال جو روزانہ بیداری کی حالت میں
Page 90
کی جاتی ہے اس میںمجاز استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور پھر ان باتوں کے بعد دنیا میںکوئی ٹھکانہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میںجو باتیںکی جاتی ہیںان میں استعارات بھی ہوتے ہیں، ان میںمجاز بھی ہوتا ہے اور کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر کلام میںمجاز استعمال کیا گیا تو دنیا میںکوئی ٹھکانہ نہیںرہے گا.غالب کا کلام پڑھ لیا جائے، ذوق کے کلام کو دیکھ لیا جائے وہ مجاز اور استعارے استعمال کرتے ہیں یا نہیں ؟ اور کیا ان کے کلام کے بعد دنیا میںکوئی ٹھکانہ رہتا ہے یا نہیںرہتا؟ ہم تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر روزانہ مجاز اور استعارے اپنے کلام میںاستعمال کرتے ہیںاور کوئی شخص ان کے اس طریق پر اعتراض نہیں کرتا.اگر ان کے کلام کے بعد دنیا میںٹھکانہ قائم رہتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کا کلام ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں مجاز یا استعارہ آجائے تو دنیا میںکوئی ٹھکانہ نہیںرہتا ؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معترضین خدا تعالیٰ کے کلام کو اتنی خوبیوں کا حامل بھی نہیںسمجھتے جتنی خوبیاں ان کے نزدیک انسانی کلام میں موجود ہونی چاہئیں.خدا تعالیٰ اپنے کلام میںمجاز اور استعارہ استعمال کرے تو انہیں اعتراض سوجھ جاتا ہے لیکن اگر بڑے بڑے ادیبوں کے کلام میںمجاز اور استعارہ استعمال ہو تو اس وقت وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیںکہ یہ بڑا فصیح کلام ہے.وہ یہ نہیں کہتے کہ مجاز اور استعارہ کے استعمال کی وجہ سے ہمیںا س کلام کے سمجھنے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جب مجاز اور استعارہ استعمال کر لیا گیا ہے تو پھر تو کلام کا اعتبار اٹھ گیا.وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ مجاز اور استعارہ کے استعمال کی وجہ سے زبان بگڑ گئی ہے بلکہ وہ اس کلام سے مزہ اٹھا تے ہیں.اس کی بلاغت کی تعریف کرتے ہیں اور اسے سارے کلام پر ترجیح دیتے ہیں آخر غالب کو دوسروں پر کیا فوقیت حاصل ہے یا ذوق کو دوسروں پر کیا فوقیت حاصل ہے یہی کہ وہ مجاز اور استعارہ میں حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور لوگ سن کر کہتے ہیں کہ غالب اور ذوق نے کمال کر دیا.مگر یہ عجیب بات ہے کہ جسے عام کلام میں اعلیٰ درجے کا کمال سمجھا جاتا ہے وہ کمال اگر الٰہی کلام میںآجائے تو کہتے ہیںکہ پھر تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا.جب عام بول چال جو بیداری میں کی جاتی ہے اس میںبھی مجاز کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو پھر وحی میںکیوںنہ ہو؟ استعارہ اور مجاز تو بلاغت کی جان ہوتے ہیں کلام الٰہی ان کے بر محل استعمال سے کیوں محروم ہو؟ ہاں جس طرح انسانی بول چال میںمجاز اور استعارہ کے باوجود غلطی سے بچنے کے ذرائع موجود ہیں ایسے ہی ذرائع کلام الٰہی کو بھی حاصل ہیں.ان کی موجودگی میں عقلمند کو دھوکا نہیںلگ سکتا اور بے وقوف کو تو ہر بات سے دھوکا لگ سکتا ہے.جیسے ایک بےوقوف کی مثال ہے کہ اس نے یہ سن کر کہ اگر بتادو میری جھولی میںکیا ہے تو ان میںسے ایک انڈا تم کو دے دوں کہا کہ کچھ اتہ پتہ بتائو تو بتائوں.حقیقت یہ ہے کہ جو ذرائع انسانی کلام میںغلطی سے محفوظ
Page 91
رہنے کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں وہی کلام الٰہی کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں.آخر یہ صاف بات ہے کہ جب مجاز استعمال کیا جائے گا تو لازماً اس کا کوئی نہ کوئی قرینہ ہو گا.قرینہ کے بغیر ہی اگر مجاز استعمال ہونے لگے تو پھر بے شک دنیا میں اندھیر پڑجائے.مثلاً اگر میں کہوں کہ کل فلاںوفات یافتہ شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یوں کہا تو چونکہ وہ صاحب فوت شدہ ہوں گے اس لئے میری یہ بات حقیقت پر مشتمل نہیں سمجھی جائے گی.لیکن اگر میں کہوں کہ کل فلاں صاحب (جو زندہ ہوں) میرے پاس آئے.اور یہ بات سن کر بعض لوگ جھگڑا شروع کر دیں ایک کہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب میں آئے تھے اور دوسرا کہے کہ نہیںظاہر میںآئے تھے تو یہ بےوقوفی ہو گی.کیونکہ پہلے قول میںیہ قرینہ موجود تھا کہ جن صاحب کا ذکر تھا وہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ بہر حال خواب میںہی آسکتے ہیں ظاہرمیں نہیں.لیکن دوسرے قول میں یہ قرینہ نہیں.پس مجاز اور استعارہ جب بھی کلام میں استعمال کیا جائے گا.اس کے لئے قرائن کا ہونا ضروری ہو گا تا کہ ہر شخص سمجھ سکے کہ جو بات بیان کی جارہی ہے وہ کلام حقیقت ہے یا کلام مجاز.لیکن بہر حال دنیا میںہمیشہ مجاز اور استعارات استعمال کئے جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ لوگوں پر ان استعمالات کی وجہ سے کسی کلام کا سمجھنا مشتبہ ہو جائے وہ ایسے کلام سے نہایت لطف اٹھاتے اور استعارات کو فصاحت کی جان قرار دیتے ہیں.پس جس طرح مجاز اور استعارہ انسانی کلام میںچار چاند لگا دیا کرتا ہے اسی طرح الٰہی کلام میں بھی مجاز اور استعارات کا استعمال اس کے حسن کو دوبالا کر دیتے اور اس کی شان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں.پس یہ بالکل غلط خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میںمجازا ور استعارہ نہیں ہوتا یا مجاز اور استعارہ کے استعمال سے حقیقت چھپ جاتی ہے.مجاز اور استعارہ پہچاننے کے دنیا میںکچھ قواعد مقرر ہیں.جو بند وں کے کلام پر بھی چسپاں ہو سکتے ہیں.اور خدا تعالیٰ کے کلام پر بھی.اگر ان قواعد کے مطابق مجاز و استعارہ کا استعمال بتایا جائے گا تو ماننا پڑے گا کہ وہ معنے درست ہیں اگر ان کے خلاف معنے کئے جائیں گے تو ان معنوں کو غلط قرار دیا جائے گا شبہ پید اہونے کا کوئی سوال ہی نہیں.يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا١ۙ۬ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْؕ۰۰۷ اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں جمع ہوں گے تاکہ (اپنی) اپنی کوششوں (کے نتائج) کو دیکھیں.حلّ لُغات.اَشْتَاتًا.اَشْتَاتًا کے معنے ہیں متفرقین یعنی گروہ در گروہ.تفسیر.يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ کی تشریح پہلے علماء کے نزدیک مفسرین نے اس کے
Page 92
معنے آخرت کے لحاظ سے کئے ہیں.چونکہ انہوں نے تمام سورۃ کو آخرت پر چسپاں کیا ہے اس لئے اس کے معنے بھی انہوں نے نیک و بد، جنتی و دوزخی اور سفید و سیاہ کے کئے ہیں.( روح المعانی سورۃ الزلزال زیر آیت يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ) مگر سفید و سیاہ سے انگریز اور ہندوستانی مراد نہیں بلکہ ان کا اشارہ يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّ تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ( اٰل عمران:۱۰۷) کی طرف ہے کہ آخرت میںکچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کچھ سرخ رو ہوں گے کچھ زیر الزام آئیں گے ( دیکھ لو یہیں مجاز آگیا) اسی طرح وہ اَشْتَاتًا کے معنے دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے کے کرتے ہیں.يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ میں آخری زمانہ کے متعلق ایک پیشگوئی میں چونکہ اسے آخری زمانہ کے متعلق سمجھتا ہوں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ مقدر تھی اس لئے میں اس کے یہ معنے کرتا ہوں کہ اس وقت جتھہ بندی زوروں پر ہو گی.اور پارٹی بازی بہت ہو گی.يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا یہ ایک خاص علامت ہے جو پہلے کسی زمانہ میں رونما نہیں ہوئی صرف موجودہ زمانہ ہی ایسا ہے جس میں یہ علامت نمایا ں طور پر نظر آتی ہے.پہلے زمانوں میں صرف منفرد کوششیں کی جاتی تھیں.اجتماع اور اتحاد کا رنگ ان میں مفقود تھا.اس زمانہ میںایک اچھے تاجر کے صرف اتنے معنے تھے کہ زید نے کچھ روپیہ لیا اور اس نے اپنے شہر میںتجارت شروع کر دی.یا اچھے صناع کے معنے صرف اتنے تھے کہ فلاں ترکھان اچھی چیزیں بناتا ہے یا فلاں لوہار لوہے کا کام خوب جانتا ہے یا مزدور کے معنے صرف اتنے تھے کہ ایک غریب شخص کسی امیر کے ہاں ملازم ہو گیا یا اس کا کوئی اور کام معین معاوضہ پر کرنے لگا اس زمانہ میںبھی بے شک مزدور بعض دفعہ آقا سے لڑ رہا ہوتا تھا اور اگر آقا کو غصہ آتا تو وہ مزدور پر اپنا غصہ نکال لیتا.مگر بہر حال ہر تاجر، ہر صناع، ہر مزدور اور ہر سرمایہ دار انفرادی جدوجہد کرتا تھا.اسے اپنے ہم پیشہ دوسرے لوگوں کے حقوق اور ان کے مطالبات سے کوئی تعلق نہیںہو تا تھا زید چاہتا تھا کہ میرا معاملہ سدھر جائے اور بکر چاہتا تھا کہ میرا معاملہ سدھر جائے مگر قرآن کریم اس جگہ یہ خبر دیتا ہے کہ آخری زمانہ میںیہ اختلافات جتھہ بندی کی شکل اختیار کر لیں گے اور پارٹی سسٹم بہت ترقی کر جائے گی.اور لوگ یہ پارٹی بازی اس لئے کریں گے لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ کہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھیںیعنی انہیںیقین ہو گا کہ جتھہ بندی سے کام کرنے کے نتائج اچھے نکلتے ہیں.اگر جتھہ بندی نہیں ہو گی تو ہمارے کام کا کوئی نتیجہ نہیںنکلے گا پہلے زمانہ میںمزدور اگر آقا کے رویہ سے بہت تنگ آجاتا تو وہ کہہ دیا کرتاتھا کہ میری مزدوری مجھے دے دیں میںچلا جاتا ہوں.مگر اس زمانہ میں جب مزدوروں نے دیکھا
Page 93
کہ اس طرح مالکوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ زید کا نوکر زید کے پاس جائے، بکر کا نوکر بکر کے پاس جائے، خالد کا نوکر خالد کے پاس جائے اور انفرادی رنگ میں اپنا مطالبہ پیش کر ے سب اکٹھے ہو جائو اور مل کر اپنے حقوق کا سوال اٹھا ئو.چنانچہ زید کا نوکر اور بکر کا نوکر اور خالد کا نوکر اور سلیم کا نوکر اور حامد کا نوکر سب اکٹھے مل جاتے ہیں اور وہ اپنی ایک ایسوسی ایشن قائم کر لیتے ہیں.جب کسی مطالبہ کا وقت آئے تو سارے نوکر مل جاتے ہیںاور متحدہ طور پر اپنے حقوق کے متعلق شور مچانا شروع کر دیتے ہیں مثلاً تنخواہ بڑھانے کا سوال ہو تو بجائے اس کے کہ زید کا نوکر زید سے، بکر کا نوکر بکر سے اور خالد کا نوکر خالد سے الگ الگ مطالبہ کرے سب مل کر اپنے مالکوں کے سامنے متحدہ طور پر مطالبہ رکھ دیتے ہیں.اور مالک مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے حق کو تسلیم کریں.پس فرماتا ہے يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا اس دن انفرادی جدوجہد کی بجائے تما م لوگ جتھہ بندی کر کے آئیںگے اور اس لئے آئیںگے لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ تا کہ ان کے اعمال ان کو دکھائیںجائیں.یعنی ان کے فعل کا نتیجہ نکل آئے.انفرادی رنگ میںکوشش کرنے سے چونکہ ہر شخص کی طاقت ضائع چلی جاتی تھی اور کوئی اچھا نتیجہ برآمد نہیںہوتا تھا اس لئے وہ اس دن جتھہ بندی اور پارٹی سسٹم کی طرف مائل ہو جائیںگے اور متحدہ محاز قائم کر کے اپنے مطالبات پیش کریں گے تا کہ ان کی آواز میںاثر پیدا ہو اور وہ مطالبات جو ان کی طرف سے پیش کئے جائیں ان کو قبول کرنے کے لئے دوسرے لوگ تیار ہوں چنانچہ دیکھ لو کنسرویٹو، لبرل، لیبر، ڈیموکریٹ، ری پبلکن، راڈیکل، نہلسٹ، نیشنلسٹ، سوشلسٹ، ناٹسی، فاسی، فلانجے، کمیونسٹ، مہاسبھا، کانگریسی، مسلم لیگی، یونی نسٹ، وفدسٹ، سعد سٹ وغیرہ وغیرہ ہزاروں پارٹیاں دنیا میںبن رہی ہیں اور سب ایک ہی وجہ بتاتے ہیں کہ بغیر جتھہ کے اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا.اجتماعی جدو جہد پس فرماتا ہے يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ.لوگ اس زمانہ میں پارٹیاں بنا کر اس لئے کام کریں گے تا کہ ان کے کاموں کے اچھے نتیجے نکلیں.بے شک یہ خیالات دنیا میں پہلے بھی موجود تھے اور یہی چیزیں جو آج دنیا میں نظر آتی ہیںپہلے بھی پائی جاتی تھیں.پہلے بھی کئی مزدور تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیںاور کئی آقا اپنے ملازموں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے ذرا بھی گستاخی کی تو تمہیں کان پکڑکر نکال دیا جائے گا.مگر پہلے زمانہ اور اس زمانہ میںفرق یہ ہے کہ پہلے پارٹی بازی اور جتھہ بندی نہیں تھی اب ہر گروہ نے اپنی الگ الگ تنظیم کر کے الگ الگ سوسائٹیاں قائم کر لی ہیں.ایک طرف ایمپلائز ایسوسی ایشن
Page 94
ہوتی ہے تو دوسری طرف ایمپلائرز ایسوسی ایشن کام کر رہی ہوتی ہے.ایک طرف ریلوے اونرز ایسوسی ایشن بنتی ہے تو دوسری طرف ریلوے ایمپلائز ایسوسی ایشن قائم ہوجاتی ہے.اسی طرح کسی جگہ کول مائنرز ایسوسی ایشن قائم ہے تو کسی جگہ کول اونرز ایسوسی ایشن کام کر رہی ہے.غرض ایک دوسرے کے مقابلہ میںسوسائٹیاں بن چکی ہیں.ایک نوکروں کی ایسوسی ایشن ہے تو ایک مالکوں کی.ایک ان لوگوں کی ایسوسی ایشن ہے جو سیاسیات میں غالب ہیںتو ایک ان لوگوں کی ایسوسی ایشن ہے جو سیاسیات میںمغلوب ہیںگویا ہر طرف جتھہ بن گیا ہے اور اب فردفرد کوشش نہیںکرتا بلکہ گروہ گروہ کوشش کرتا ہے یہی خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میںدی کہ يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا اس دن فرد فرد کوشش نہیںکرے گا بلکہ گروہ گروہ کوشش کرے گا.لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ تا کہ ان کی کوششوں کے اچھے نتائج برآمد ہوں اور وہ اپنی قوتوں کو ضائع کرنے والے نہ ہوں.اس جگہ ھُمْ کی ضمیر اسی لئے لائی گئی ہے کہ اس میں متعدد گروہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہر گروہ اپنے اپنے حقوق کے متعلق جدوجہد کرے گا.لیبر مل کر کوشش کریں گے کہ لیبر کے حق میںنتیجہ نکل آئے.سوشلسٹ مل کر کوشش کریں گے کہ سوشلسٹ کے حق میںنتیجہ نکل آئے نیشنلسٹ مل کر کوشش کریں گے کہ نیشنلسٹ کے حق میں نتیجہ نکل آئے.کمیونسٹ مل کر کوشش کریں گے کہ کمیونسٹ کے حق میںنتیجہ نکل آئے.غرض ہر پارٹی جتھہ بازی کے ذریعہ اپنے حقوق کو حاصل کر نے کی جدوجہد کرے گی.چنانچہ آج دنیا میںہزاروں پارٹیاں بن رہی ہیںاور کتابوں میںصاف طور پر لکھا جاتا ہے کہ پہلے زمانوں میں ناکامی کی بڑی وجہ یہی تھی کہ مل کر کام نہیںکیا جاتا تھا اب ہم مل کر کام کریںگے اور اپنی آواز کو زیادہ سے زیادہ موثر اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں گے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے ہمارا بھی یہی منشاء تھا کہ انفرادی کوشش کی جگہ اس دن قومی کوشش ہو تا خوب اچھی طرح خیر و شر کا فرق ظاہر ہو جائے.اس جگہ لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ میںجہاں بندوں کی طرف سے اپنے حقوق کے لئے جدوجہد شروع ہونے کا ذکر ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کی تائید کا اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جہاں وہ اپنے اپنے دائرہ اور اپنے اپنے رنگ میںکوشش کررہے ہوں گے وہاں خدا تعالیٰ بھی کوشش کر رہا ہو گا.یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَكَرُوْا وَ مَكَرَ اللّٰهُ١ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.(اٰلِ عـمران: ۵۵) انہوں نے بھی تدابیرکیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیرکی اور اللہ تعالیٰ تمام تدابیر کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہے.اسی طرح فرماتا ہے لوگ یہ تجویزیں کریں گے کہ ہم مل کر کام کریں اور ہم بھی ان کو پوری طرح موقع دیں گے تا کہ ان کے دلوں میں کوئی حسرت نہ رہے اور لوگ قومی طورپر اپنے حوصلے نکال کر آخر اس امر کو تسلیم کریں کہ قانون اور پارٹی وہی اچھی ہے جسے خدا تعالیٰ بنائے.
Page 95
پہلے زمانہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ابو جہل اٹھا اور وہ اپنی تمام کوششوں اور منصوبہ بازیوں کے باوجود ناکام و نامراد ہوا اور ناکامی و نامرادی کی حالت میںہی مرا.تو گو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا نشان تھا جو ظاہر ہوا اور جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو آفتاب نصف النہار کی طرح ظاہر کر دیا مگر پھر بھی یہ انفرادی مقابلہ تھا قومی نہیں.قومی مقابلہ ہجرت کے بعد شروع ہوا جس نے کفار عرب کی مجموعی طاقت کو توڑ دیا.اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میںبے شک آپ کا شدید مقابلہ ہوا مگر اس وقت مقابلہ کی تمام تر صورت انفرادی جدوجہد تک محدود تھی.مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی الگ مقابلہ کر رہے تھے.مولوی ثناء اللہ صاحب الگ مقابلہ کر رہتے تھے.مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی الگ مقابلہ کر رہے تھے.بےشک اَلْکُفْرُ مِلَّۃٌ وَّاحِدَۃٌ کے مطابق ان تمام کے تیروں کا نشانہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہی ذات تھی لیکن بہر حال انہوں نے آپ کا اکٹھا مقابلہ نہیں کیا.ہر شخص الگ الگ شہر میںالگ الگ رنگ میں مقابلہ کر رہا تھا.مولوی محمد حسین صاحب کسی رنگ میں مخالفت کر رہے تھے تو مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کسی اور رنگ میں.احمدیت کے مقابلہ پر اجتماعی جدوجہد مگر چونکہ یہ زمانہ وہ تھا جس میں يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا کی پیشگوئی کا ظہور ہونے والا تھا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ۱۹۳۴ ء میںاحرار کو جماعت احمدیہ کے مقابلہ کے لئے کھڑا کر دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جماعت احمدیہ کو کچل کر رکھ دیں گے.پہلے کیا تھا، پہلے کوئی لدھیانہ میں مخالفت کر رہا تھا.کوئی لاہور میںمخالفت کر رہا تھا کوئی دہلی میں مخالفت کر رہا تھا کوئی بٹالہ میں مخالفت کر رہا تھا.اب ہم مل کر احمدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیںگے (تاریخ احرار صفحہ ۱۲۶)چنانچہ احرار کے ساتھ کانگرس بھی مل گئی.اور پھر کسی مصلحت کے ما تحت حکومت بھی ان کے ساتھ مل گئی.یہ مخالفت کا طوفان درحقیقت مظاہرہ تھا يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا کا.لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ خدا تعالیٰ کے فضل اور حمایت ِ احمدیت کو ظاہر کر رہا ہے.اب شیعوں نے ہمارے مقابلہ میں سر نکالنا شروع کر دیا ہے.اور وہ بھی احرار کی طرح یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کو کچل دیںگے.غرض وہ مقابلہ جو پہلے انفرادی رنگ میںکیا جاتا تھا اب قومی مقابلوں کے رنگ میں تبدیل ہو چکا ہے اور احمدیت اپنی جدوجہد کے سلسلہ میںاسی منزل میں سے گذر رہی ہے.
Page 96
فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗؕ۰۰۸ پھر جس نے ایک ذرہ کے برابر (بھی ) نیکی کی ہوگی وہ اس (کے نتیجہ) کو دیکھ لے گا.وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗؒ۰۰۹ اور جس نے ایک ذرہ کے برابر (بھی )بدی کی ہو گی وہ اس (کے نتیجہ ) کو دیکھ لے گا.تفسیر.فرماتا ہے لوگوں کے اکٹھا کام کرنے سے ہمارے اس قانون کی سچائی ثابت ہو گی کہ جو شخص ایک ذرہ بھر بھی عمل خیر دوسروں کے ساتھ مل کر کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا اور جو شخص ایک ذرہ بھر بھی عمل شر دوسروں کے ساتھ مل کر کرے گا وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا.یعنی اس زمانہ میںچونکہ ہر شخص اپنی پارٹی سے مل کر کام کرے گا اس لئے ہر قسم کے کام کا نتیجہ نمایا ں نکلے گا.کیونکہ مشترک کام ذرہ ذرہ مل کر بھی پہاڑ ہو جاتا ہے الگ کیا ہوا کام ذرہ کے مطابق ہو تو اس کا نتیجہ محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ ذرہ بھر کام جو قوم کے ساتھ مل کر کیا ہو چھپ نہیںسکتا کیونکہ دوسروں کے ذروں سے مل کر وہ پہاڑ بن جاتا ہے.پس فرماتا ہے چونکہ اس دن پارٹیاں مل کر کام کریںگی ہر کام کا نتیجہ نمایا ں نظر آئے گا اور عمل کاایک ذرہ بھی ضائع نہیںہو گا اس میںکوئی شبہ نہیں کہ انسانی عمل کا ایک ذرہ دنیا میں کوئی قیمت نہیںرکھتا اور وہ ہوا میں اڑ کر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے لیکن جب ایک گروہ کا گروہ اپنا اپنا ذرہ لے آئے تو ہر ذرہ دوسرے ذرات کے ساتھ مل کر ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح کوئی ذرہ بھی نمایاں ہونے سے نہیںرہ سکتا.یہ مضمون در حقیقت گذشتہ آیت کے تسلسل میںہی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ اس دن يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا کا کیوں ظہور ہو گا.فرماتا ہے یہ ظہور اس لئے ہو گا تا ہمارے اس قانون کی سچائی نمایاں ہو جائے کہ دنیا میںجو شخص چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے خواہ وہ عمل خیر ہو یا عمل شر اگر انفرادی اعمال خیر اور انفرادی اعمال شر پر اس آیت کو چسپاں کیا جائے تو اس کے کوئی معنے ہی نہیںبنتے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کا عمل خیر اور ہر شخص کا عمل شر نمایا ں ہو گااور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیںلیکن دنیا میںایسا نہیںہوتا.دنیا میں لوگ بڑے بڑے خیر کے کام کرتے ہیں اور وہ چھپے رہتے ہیں.اسی طرح بڑے بڑے شر کے کام کرتے ہیں اور وہ چھپے رہتے ہیں.اگر دنیا میںہر خیر اور ہر شر نمایاں ہو تو لوگوں کو گناہوں پر دلیری ہی کیوں پیدا ہو.ہزاروں لوگ ایسے پائے جاتے ہیںجو بڑے بڑے خیر کے کام کرتے ہیں مگر چونکہ وہ فرداً
Page 97
فرداً کرتے ہیں ان کا کوئی ایسا نتیجہ نہیںنکلتا جس سے لوگوں کے دلوں میںخیر کی تحریک پیدا ہو.اسی طرح ہزاروں ہزار لوگ شر کرتے ہیں مگر چونکہ وہ فرداً فرداً کرتے ہیں اس لئے ان کے شر کا کوئی ایسا نتیجہ نہیںنکلتا جس کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہو جائیں اور اعمال شر کو ہمیشہ کے لئے ترک کر دیں.مگر فرماتا ہے ہم جس زمانہ کی خبر دے رہے ہیں اس میںخیر کرنے والے بھی اپنے اپنے عمل کا ذرہ لا کر ایک جگہ ڈال دیں گے اور شر کرنے والے بھی اپنے اپنے عمل کا ذرہ لا کر ایک جگہ ڈال دیں گے.اس کا طبعی طور پر یہ نتیجہ نکلے گا کہ جب ساری دنیا کے خیر اکٹھے ہو جائیںگے تو وہ بھی ایک پہاڑ بن جائیں گے اور جب ساری دنیا کے شر اکٹھے ہو جائیںگے تو وہ بھی ایک پہاڑ بن جائیںگے.گویا ان الفاظ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ا س دن کفر و اسلام کا نظامی مقابلہ ہو گا ایک طرف کفر اپنے تمام لشکر کو اکٹھا کر کے نظام قائم کرے گا اور دوسری طرف اسلام کے احیاء اور اس کی تقویت کے لئے اعمال خیر کرنے والوں کا ایک نظام قائم کیا جائے گا اور پھر ان دونوں نظاموں کا آپس میںٹکرائو ہو گا.کفر چاہے گا کہ وہ اسلام کو ختم کر دے اور اسلام چاہے گاکہ وہ کفر کو تباہ کر دے یہ پیشگوئی جو ان آیات میںکی گئی ہے اس پر غور کر کے دیکھ لو پہلے کسی زمانہ میںیہ پوری نہیںہوئی.نہ کفرنے اجتماعی مقابلہ کے لئے کوئی نظام قائم کیا اور نہ اسلام میںکفر کا سر کچلنے کے لئے کوئی باقاعدہ نظام قائم ہوا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی چندہ کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ صحابہ ؓ کو اکٹھا فرماتے اور ان کے سامنے چندے کا اعلان کر دیتے.صحابہ ؓ اسی وقت اپنی اپنی توفیق کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میںاپنا چندہ پیش کر دیتے.یہ نظر نہیںآتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیت المال قائم کیا ہو اور ایک نظام کے ماتحت جماعت کے ہر فرد سے باقاعدہ چندہ وصول کیا جاتا ہو.مگر اس زمانہ میںحضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابتدائے دعویٰ میں ہی پانچ مدات قائم فرما دیںجن کا ’’فتح اسلام ‘‘میںتفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے.اور لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اسلام کے احیاء اور اس کی ترقی کے لئے ان مدات میںروپیہ ارسال کریں.گویا آپ نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی ایک نظام کی بنیادرکھ دی اور پھر رفتہ رفتہ اس کی بنیادوں کو اور بھی پختہ اور مضبوط بنا دیا یہاں تک آپ نے اعلان فرما دیا کہ جوشخص تین ماہ تک اس سلسلہ کے لئے کوئی روپیہ ارسال نہیںکرتا اس کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیںسمجھا جا سکتا(مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ ۴۶۹).غرض اسلام کے احیاء کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرما دیا ہے ادھر کفر نے بھی اپنی طاقتیں جمع کر لی ہیں اور وہ اسلام کو کچلنے کے لئے مختلف قسم کی تدابیر میں منہمک ہے.مسیحیت کی تبلیغ، آریہ سماج کی تبلیغ، سکھوں کی تبلیغ، یہودیت کی تبلیغ انفرادی طور پر نہیں ہو رہی بلکہ بڑی بڑی سوسائٹیاں لاکھوں کروڑوں روپیہ جمع کر کے باقاعدہ طور پر کر رہی ہیں.پس فرماتا ہے جب وہ آخری زمانہ آئے گا جس میں
Page 98
ہمارے رسول کی بعثت ثانیہ مقدر ہے توہم ادھر خیر کرنے والوں کو کہیں گے کہ تم اکٹھے ہو جائو.ادھر شر کرنے والوں کو ملائکہ تحریک کریں گے کہ تم اکٹھے ہو جائو.اس طرح کفر و اسلام کا عظیم الشان ٹکرائو ہو گا جس میں آخر اسلام کو فتح ہو گی اور یہ سب کچھ ہم اس لئے کریں گے تا دنیا کے لوگ یہ نہ کہہ سکیںکہ ہم تو غافل رہے ہمیں تو اپنے دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ہی نہیں ملا.اگر ملتا تو ہم اسلام کو کبھی ترقی کرنے نہ دیتے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کفر کے دل میں کوئی حسرت باقی رہ جائے اسے اپنے حوصلے نکالنے کا موقع نہ ملے اور وہ کہہ سکے کہ اگر مجھے تیاری کا موقع ملتا تو میں بتا دیتا کہ اسلام دنیا میں نہیں پھیل سکتا.ہم اسے پوری طرح موقع دیں گے اور اعمال شر کرنے والے اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوں گے.وہ خوب سمجھتے ہوں گے کہ وہ کیا مقصد لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے کیا کیا ارادے ہیں.اسی طرح اعمال خیر کرنے والے بھی اپنی ذمہ واریوں سے اچھی طرح آگاہ ہوں گے.اس وجہ سے کفر و اسلام کی اس باہمی ٹکر کا جو نتیجہ نکلے گا وہ آخری اورقطعی ہو گا اور شر کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ مجھے خیر کے مقابلہ کی فرصت نہیں ملی.فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کے معنے ترتیب مضمون کے لحاظ سے یہ تو دینی معاملہ کی میں نے مثال پیش کی ہے اگر دنیوی مثالیں لے لو تب بھی یہ تمہیںنظر آئے گا کہ جس طرح اس زمانہ میں مختلف پارٹیوں کی صورت میں مل کر کام کیا جاتا ہے اس کی پہلے زمانہ میں کوئی نظیر نہیں ملتی.مثلاً جہاں تک ظالم لوگوں کی موجودگی کا تعلق ہے یہ عنصر صرف اس زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر زمانہ میں ظالم لوگ ہوتے رہے ہیں اور ہر زمانہ میں لوگوں کو ان سے شکائتیں ہوتی رہی ہیں.چنانچہ پہلے زمانوں میں بھی کئی ایسے نوکر ہوتے تھے جو اپنے آقائوں کو مار ڈالتے تھے.ہزاروں واقعات ایسے پائے جاتے ہیں کہ آقا نے اپنے نوکر کو کسی بات پر گالی دی تو اس نے برا منایا اور رات کو جب وہ سورہا تھا اسے قتل کر دیا.مگر اس کا کوئی گہرا یا دیر پا اثر نہیں ہوا کرتا تھا زیادہ سے زیادہ یہی سمجھا جاتا کہ زید کو اس کے نوکر نے قتل کر دیا ہے یا بکر کو اس کے نوکر نے قتل کر دیا ہے.دنیا کو اس کا کوئی نتیجہ نظر نہیںآتا تھا کیونکہ یہ کام اور دوسرے کاموں میں چھپ جاتا.مگرا س زمانہ میں جب روس میں کمیونسٹوں نے سر اٹھایا اور انہوں نے مل کر اپنے مالکوں کو مار ڈالا تو اس کا کتنا عظیم الشان نتیجہ نکلا کہ حکومت ہی بدل گئی.اسی طرح مزدور نا خوش ہو کر پہلے زمانہ میں بھی کام چھوڑ دیا کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ دنیا میںکیا تغیر ہوا ہے لیکن اس زمانہ میں لیبر سٹرائکس کے ذریعہ سے مالکوں کی گردنیںیوں جھک جاتی ہیں کہ خدا یاد آجاتا ہے.یہی حال سود کا ہے.سود لوگ لیتے ہی چلے آئے ہیں لیکن اس زمانہ میںبنکو ں کے ذریعہ سے دنیا کو اس طرح قابوکر لیا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ.
Page 99
پہلے کسی گائوں کے ایک کونہ میںبیٹھ کر بنیا چند لوگوں سے سود لیتا اور کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا تھا مگر اب ایسے بنک نکل آئے ہیںجن کی ساری دنیا میں شاخیں ہیں اور اس طرح سود کا جال وسیع کر کے ساری دنیا کو قابو کر لیا گیا ہے.صنعت و حرفت بھی ہمیشہ سے چلی آتی ہے لیکن اب کمپنیوں کے ذریعہ سے اس طرح دوسرے ملکوں کا دیوالہ نکالا گیا ہے کہ غریب حیران و پریشان نظر آتے ہیں.پہلے زمانہ میں صرف معمولی تاجر ہوا کرتے تھے لیکن اس زمانہ میں کمپنیاں نکل آئی ہیں.پہلے خواہ کوئی کتنا بڑا تاجر ہو جائے لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں لگتا تھا اور وہ لوگوں کی دولت کو بھی زیادہ نہیں کھینچ سکتا تھا.مگر اس زمانہ میں کمپنیوں نے اس طرح دولت کھینچی ہے کہ بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ کمپنیوں میں ملازمت اختیار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ انہیںگورنمنٹ سروس میںکوئی جگہ ملے.لارڈ مانڈ انگلستان کا وزیر خزانہ تھا مگر وزارت چھوڑ کر وہ امپیریل کیمیکل انڈسٹری میںملازم ہو گیا.اسی طرح ایک او ر مشہور شخص غالباً سر کینر نام تھا وہ بھی پہلے وزیر خزانہ تھا مگر پھر اس عہدہ سے الگ ہو کر ریلوے کمپنی میں ملازم ہو گیا.وزارت کے عہدہ کی صورت میںاسے پانچ ہزار پونڈ ملتے تھے مگر ریلوے کمپنی میںملازمت اختیار کرنے پر اسے تیس ہزار پونڈ ملنے لگ گئے گویا قریباً پانچ لاکھ روپے سالانہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا.غرض کمپنیوں نے تجارت اور صنعت و حرفت کے ذریعہ اس قدر دولت کھینچی ہے کہ پرانے زمانہ میں کسی بڑے سے بڑے صناع او ر بڑے سے بڑے تاجر کی بھی اتنی آمد نہیںہوتی تھی جتنی آج کل کمپنیوں کے نوکروں کو تنخواہیں ملتی ہیں.پھر کمپنیوں سے ترقی کر کے ٹرسٹ بن گئے ہیں.اور ٹرسٹ سے ترقی کرکے کارٹل بن گئے ہیںاس طرح ہر کام لوگوں نے اجتماعی رنگ میںشروع کر کے اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے.غرض يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا نے یعنی ایک دوسرے کے بالمقابل ایک ایک کر کے نکلنے کی جگہ پارٹی پارٹی بن کر نکلنے نے وہ نمونہ دکھایا ہے کہ دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا.یہ پارٹیاں خیر کا کام کرتی ہیں تو وہ بھی ایک عظیم الشان شکل میںظاہر ہوتا ہے اور اگر برا کام کرتی ہیں تو وہ بھی ایک مہیب اور دل پر کپکپی نازل کر دینے والی شکل میں نظر آتا ہے.چونکہ مومن بھی اس دن مل کر کام کریں گے اس لئے ان کے خیر کے نتائج بھی بڑے شاندار ہوں گے بلکہ چونکہ خیر کا دس گنا اجر ہے اس لئے ان کے خیر کے نتائج شر کے نتائج پر غالب آجائیںگے.فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کے معنے ترتیب آیات کے علاوہ یہ معنے تو ترتیب کے لحا ظ سے ہوئے.یوں بھی اپنی ذات میںیہ آیت نہایت اہم ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی نسبت فرماتے ہیں آپ سے گدھوں کے بارہ میں پوچھا گیا کہ ان کے رکھنے کا کیا ثواب ہے تو فرمایا مَا اَنْزَل اللہُ فِیْـھَا شَیْئًا اِلّ
Page 100
ھٰذِہِ الْاٰیَۃَ الْفَازَّۃَ الْـجَامِعَۃَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.فَازَّۃٌ کے معنے ہیں منع کرنے والی اور جَامِعَۃٌ کے معنے ہیں سمیٹنے والی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارہ میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فازہ اور جامعہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ یعنی ہر چیز جس کو نکالنا مقصود ہے اس کو اس آیت کے ذریعہ نکال دیا گیا ہے اور ہر چیز جس کو سمیٹنا مقصود ہے اس کو اس آیت کے ذریعہ سمیٹ لیا گیا ہے.گویا یہ آیت جزائے خیر و شر کے متعلق ایک جامع مانع قاعدہ پر مشتمل ہے.جزائے خیر اور جزائے شر سے تعلق رکھنے والی کوئی بات نہیںجو اس میں بیان نہ کی گئی ہو اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ دنیا میں انسان ہزاروں کام خیر یا شر سے تعلق رکھنے والے کرتا ہے مگر وہ خیر اور شر کے سب کام مٹ جاتے ہیں اور کسی کو علم بھی نہیںہوتا کہ زید نے فلاں خیر کا کام کیا تھا یا بکر سے فلاں شر کا صدور ہوا تھا.بیسیوں انسان دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بدخواہی کے خیالات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں مگر جن لوگوں کی برائی کے خیالات ہر وقت اس کے دل و دماغ میںپرورش پا رہے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ فلاں شخص ہمارے متعلق کیسے برے خیالات رکھتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جو شخص کسی کے متعلق غیبت میںکوئی برا کلمہ کہتا ہے اور ایک تیسرا شخص جو اس بات کو سن رہا ہوتا ہے اس جگہ سے اٹھ کر دوسرے شخص کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارے متعلق آج فلاں نے یہ بات کہی ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی نے دوسرے کی طرف تیر پھینکا مگر وہ تیر اس کو لگا نہیں بلکہ زمین پر گر پڑا.یہ دیکھ کر ایک اور شخص دوڑا دوڑا آیا اور اس نے وہ تیر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دوسرے کے سینہ میں پیوست کر دیا.بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہزاروں لوگ دوسروں کی بدخواہی کے خیالات اپنے دلوں میںرکھتے ہیں مگر ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیںہوتا نہ دوسروں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے متعلق فلاں شخص کیسے گندے خیالات رکھتا ہے اور نہ اس کے ان خیالات کا دنیا میں کوئی نتیجہ ظاہر ہوتا ہے.اسی طرح ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں دوسروـں کے متعلق نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں،مگر ان دوسرے اشخاص کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ فلاں شخص کو ہم سے محبت ہے یا اس کا دل ہماری ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات سے لبریز ہے.ایک شخص کو دوسرے سے غائبانہ محبت ہوتی ہے مگر اس وجہ سے کہ محبت اس کے دل میں مخفی ہوتی ہے دوسرا شخص محض بے خبر ہوتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخص میرا دوست ہےمجھ سے محبت کرتا ہے اور میری مصیبت کی گھڑیوں میں میرا ساتھ دینے والا ہے.اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو شخص آپس میں گہرے دوست ہوتے ہیں، ان کے ایک دوسرے سے مخلصانہ تعلقات
Page 101
ہوتے ہیں اور وہ مصیبت میں ایک دوسرے کے ہمیشہ کام آتے رہتے ہیں مگر اس کے باوجود ایک کو دوسرے کے اندرونی جذبات کا علم نہیں ہوتا.ان میں سے ایک شخص راتوں کو اٹھتا اور اﷲ تعالیٰ سے اس کے لئے رو رو کر دعائیں مانگتا ہے مگر دوسرے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ رات کی تاریکیوں میں جب ساری دنیا محوِ استراحت ہوتی ہے میرا دوست میرے لئے اﷲ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہے اور وہ میری بھلائی کے لئے اﷲ تعالیٰ کی رحمت کے دروازہ کو کھٹکھٹا رہا ہے.غرض دنیا میں ہمیں یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ ہزاروں ہزار اعمال خیر اور ہزاروں اعمال شر لوگوں کی نگاہ سے مخفی رہتے ہیں.لیکن فرماتا ہے اﷲ تعالیٰ کے معاملہ میں یہ بات نہیں اﷲ تعالیٰ کے حضور کسی کا خفیف سے خفیف خیر اور کسی کا خفیف سے خفیف شر بھی ضائع نہیں جاتا.وہ ہر خیر سے آگاہ ہے وہ ہر شر سے واقف ہے اور خواہ کوئی کتنا ہی حقیر اور معمولی کام ہو اس کی نگاہ سے مخفی نہیں ہو سکتا.تم مت سمجھو کہ جس طرح بنی نوع انسان کے معاملات میں تمہارے خیر کے اعمال بھی مخفی رہتے ہیں اور تمہارے شر کے اعمال بھی مخفی رہتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کا حال ہو گا ایسا ہرگز نہیں ہو گا.مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.بنی نوع انسان کے معاملہ میں بسا اوقات تمہارے خیر کے پہاڑ بھی غائب ہو جاتے ہیں اسی طرح بنی نوع انسان کے معاملہ میں تمہارے شر کے پہاڑ بھی غائب ہو جاتے ہیں.مگر خدا تعالیٰ کی نگاہ سے تمہارا کوئی عمل مخفی نہیں ہو سکتا.دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص عملِ شر کرے اور دوسرے لوگوں سے مخفی رہے مگر خدا تعالیٰ کے حضور ایسا نہیں ہو سکتا.مثلاً دنیا میں ہزاروں واقعات ایسے ہو تے رہتے ہیں کہ بعض لوگ دوسروں کو چوری چھپے زہر دے دیتے ہیں اور باوجود تلاش و جستجو کے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے زہر دی.اسی طرح ہزاروں قاتل ایسے ہوتے ہیں جو پکڑے نہیں جاتے.اب جہاں تک شر کا تعلق ہے قاتل نے دوسرے پر شر کا ایک پہاڑ گرا دیا مگر وہ مخفی رہا.کئی لوگ دوسرے کو جنگل میں اکیلا پا کر قتل کر دیتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ کس نے قتل کیا ہے.بالکل ممکن ہے ایک شخص دوسرے کو علیحدگی میں قتل کر کے آجائے اور پھر اسی مقتول کے بیٹے کا دوست بن جائے.وہ دونوں دانت کاٹی روٹی کھانے لگیں اس کا بیٹا اپنے دوست کے لئے جان تک دینے کے لئے تیار رہے اور اسے یہ معلوم تک نہ ہو کہ میرے باپ کو اسی شخص نے قتل کیا تھا جس سے میں محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہوں.غرض دنیا میں ہمیشہ یہ نظارے نظر آتے ہیں.کہ ایک شخص شر کا پہاڑ اٹھا کر دوسرے پر گرا دیتا ہے مگر خود اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو پتہ تک نہیں چلتا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے اور چونکہ بہت سے اعمال خیر اور بہت سے اعمال شردنیا میں ظاہر نہیں ہوتے اس لئے ضروری تھا کہ
Page 102
ایک ہستی ایسی ہوتی جس کے علم میں انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا فعل آجا تا اور وہ اس کے مطابق اس کو بدلہ دیتا تاکہ خیر کرنے والے کو یہ حسرت نہ رہے کہ میری فلاں نیکی ضائع چلی گئی اور شر کرنے والے کو یہ غرور نہ رہے کہ میں نے فلاں شر تو کیا مگر میں اس کے تلخ انجام سے محفوظ رہا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے اعمال خیر اور بہت سے اعمال شر ظاہر ہو جاتے ہیں بالخصوص وہ عمل خیر یا وہ عمل شر جو عظیم الشان ہو عام طور پر مخفی نہیں رہتا اور لوگوں کو اس کا ضرور علم ہوجا تا ہے لیکن چھوٹے گناہ اور چھوٹی نیکیا ں تو ہزاروں ایسی ہیں جو بالکل مخفی رہتی ہیں مثلاً کسی کے دل میں نیکی کا خیال آنا یہ خود ایک عمل خیر ہے اور کسی کے دل میں کسی برائی کا پیدا ہونا یہ خود ایک شرہے مگر کون دوسرے کے دل کو پھاڑ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس میں شر پید ا ہے یا عمل خیر پرورش پا رہا ہے.لیکن جب ایک زندہ اور علیم و خبیر ہستی موجود ہو تو پھر اس امر کا کوئی خدشہ نہیں رہ سکتا کہ میری نیکی مخفی رہ جائے گی یا بدی چھپ سکے گی کیونکہ وہ ہستی ہروقت انسان کی نگران ہوگی اور اس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں جانے دے گی.پھر اگر ہم انسانی اعمال پر نظر دوڑائیں اور بنی نوع انسان کی اکثریت کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسانی اعمال سب کے سب بڑے نہیں ہوتے بلکہ ان میں سے اکثر چھوٹے ہوتے ہیں.بڑا عمل کرنے کی کسی کسی انسان کو توفیق ملتی ہے ورنہ ہزاروں انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ساری عمر گذر جاتی ہے مگر ان کو کوئی بڑا کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی اور اس وجہ سے وہ نمایاں طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آتے.وہ دنیا کی نگاہوں سے مخفی رہتے اور مخفی ہونے کی حالت میں ہی اس دنیا سے گذر جاتے ہیں.ان کی حیثیت با لکل ان بوٹیوں کی سی ہوتی ہے جو پہاڑوں میں پیدا ہوتی اور کچھ عرصہ کے بعد مرجھا جاتی ہیں نہ ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی کو ان کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے.پس اگر دنیا کا کوئی خدا نہ ہوتا.اگر ایک ایسی ہستی موجود نہ ہوتی جس کی نظر انسان کے دل کے مخفی گوشوں تک وسیع ہے اور جو انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی جاننے والا اور انسان کو اس کی جزا دینے والا ہے تو وہ لوگ تو زندہ ہی مر جاتے جن کی ساری عمر گذر جاتی ہے مگر ان سے کوئی بڑا عمل ظاہر نہیں ہوتا.یہی حکمت ہے کہ اسلام نے بنی نوع انسان کو یہ مژدۂِ جانفزاسنایا کہ اس عالم کا ایک خدا ہے جس کی نگاہ میں انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام آجا تا ہے.اگر کوئی عمل خیر کرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اور اگر کوئی عمل شر کرتا ہے تو بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے.تم مت سجھو کہ تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں گے اور ان کا کوئی نتیجہ رونمانہیں ہوگا.اگر دنیا میں تمہارے اعمال خیر مخفی رہے ہیں اور کسی نے ان کو نہیں دیکھا تو تم مت گھبرائو آسمان پر ایک زندہ خدا موجود ہے جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے وہ تمہیں نیکیوں کی جزاء دے گا اور تمہارا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اس کے
Page 103
سامسامنے اسی طرح آ جائے گا جس طرح کوئی بڑے سے بڑا کام آتا ہے.غرض یہ آیت ایسی ہے جو انسانی زندگی کی کایا پلٹنے والی اور لوگوں کے قلوب میں ایک نئی امنگ،نئی روح اور نئی بیداری پیدا کرنے والی ہے اگر یہ آیت نہ اترتی تو اکثر انسان اپنے آپ کو لاوارث سمجھتے کیونکہ اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی نہ خیر عظیم الشان ہوتی ہے نہ شر عظیم الشان ہوتا ہے.پس اربوں آدمیوں کی دنیا میں اگر تم قاتل تلاش کرنے لگو تو وہ بھی تمہیں زیادہ سے زیادہ لاکھ دو لاکھ ملیں گے اور تم دیکھو گے کہ دنیا میں شر کے لحاظ سے بھی صرف چند کی طرف لوگوں کی توجہ پھرتی ہے سب کی طرف نہیں.حالانکہ ایک قاتل یا ایک ڈاکو یا ایک چور جسے برا سمجھا جاتا ہے اس کے مقابل میں اور بھی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جن سے شر ظاہر ہوتا رہتا ہے مگر لوگوں پر ان کے شر کی کیفیت مخفی رہتی ہے.مثلاً قاتل تو اپنی زندگی میں صرف ایک یا دو قتل کرتا ہے مگر ایک اور آدمی ایسا ہوتا ہے جس سے سارا دن شر ظاہر ہوتا رہتا ہے.کسی کو اچھے لباس میں ملبوس دیکھتا ہے تو اس کا دل کباب ہو جاتا ہے.کسی کو اچھا کھانا کھاتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کمبخت کا گلا بھی نہیں گھٹتا.کسی کو آرام و آسائش میں زندگی بسر کرتے دیکھتا ہے تو جل بھن کر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ مرتا بھی نہیں اس کمبخت پر کوئی بیماری بھی نہیں آتی کہ اسے بھی تکلیف کا احساس ہو.غرض سارادن اس سے شر ظاہر ہوتا رہتا ہے مگر اس کے شر کی دنیا میں کوئی نمائش نہیں ہوتی اور اسی حالت میں اس کی تمام عمر گذر جاتی ہے.اس کے مقابل میں ایک اور شخص ایسا ہوتا ہے جس کے پاس کروڑ دو کروڑ روپیہ نہیں ہوتا کہ وہ آکسفورڈ یو نیو رسٹی قائم کردے یا کوئی اور علمی ادارہ قائم کرے بلکہ اکثر لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی راہ میں چند پیسے دینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی مگر وہ سارا دن اپنے دل میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ اﷲ تعالیٰ دنیا کا بھلا کرے.اﷲ تعالیٰ دنیا کو بلائوں سے نجات دے.اﷲ تعالیٰ لوگوں کی مصیبتوں اور ان کی تکلیفوں کو دور کرے.اﷲتعالیٰ ان کے لئے اپنے فضل کے دروازے کھولے یہی دعائیں ان کے ورد زبان رہتی ہیں اور وہ اسی حالت میں دنیا سے گذر جاتے ہیں کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ان سے کیا کیا خیر ظاہر ہوتی رہی ہے اگر لوگوں کا خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ نہ ہو اور ساری دنیا اسی طرح مر جائے جس طرح پہاڑوں میں پیدا ہونے والی بوٹیاں چند دن اپنی بہار دکھا کر خاک ہو جاتی ہیں تو ان کے اعمال خیر بھی فناہو جاتے اوراعمال شر بھی فنا ہو جاتے.نہ نیکوں کو ان کی نیکی کا کوئی فائدہ پہنچتا اور نہ بدوں کو ان کی شرارتوں کا کوئی خمیازہ بھگتنا پڑتا.نیک لوگ اپنے آپ کو لاوارث سمجھتے اور برے لوگ تمرد اور سرکشی میں بڑھ جاتے اور وہ سمجھتے کہ ہم سے کوئی گر فت کرنے والا نہیں ہے جو کچھ ہمارے جی میں آئے ہم کر سکتے ہیں.قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آئے تو غلطی کرو گے مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.
Page 104
وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.ایک خدا ہے جو اس دنیا کو پید ا کرنے والا ہے اور جس کی نظر سے انسان کا باریک سے باریک عمل خیر بھی پوشیدہ نہیں ہوتا اس لئے اے کمزور اور بیمار انسان ! اے لولے لنگڑے انسان ! اے غریب اور نادار انسان ! تو مت گھبرا.آسمان پر ایک خدا تیرے حالات کو دیکھ رہا ہے اور اس کی نگاہ سے تیرا کوئی عمل پوشیدہ نہیں.اے کمزور اور نا طاقت انسان ! جو کسی کی مدد نہیں کر سکتا.اے لولے لنگڑے انسان! جو کھڑے ہوکر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا.اے بیمار اور نحیف انسان جو دینی خدمات کی ادائیگی کے لئے اپنے اندر چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تیرا دل گھبرا تا ہو گا کہ اور لوگ تو نیکیوں میں حصہ لے گئے اور میںمحروم رہ گیا.تو پریشان مت ہو تیرا دل اپنی اس بے کسی کو دیکھ کر گھبرائے نہیں تیری وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ان حالات میں تجھ سے ظاہر ہوتی ہے،تیرا چھوٹے سے چھوٹا وہ نیک خیال بھی جو تیرے دل کے اندرونی گوشوں میں پیدا ہوتا ہے اﷲتعالیٰ کے حضور وہی قدر و قیمت رکھتا ہے جو دوسروں کے بڑے بڑے اعمال خیر رکھتے ہیں.بے شک تو نے جب دین کی خدمت کے لئے ایک پیسا یا دھیلا نکال کر دیا تو لوگ تجھ پر حقارت کی ہنسی ہنسے.تو نے ایک روٹی کا ٹکڑا پیش کیا تو وہ تجھ پر مسکرائے اور انہوں نے کہا اس روٹی کے ٹکڑہ سے کیا بن جائے گا مگر تو مت گھبرا.مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.تیرے عمل خواہ کتنے حقیرہوں،تیری کوششیں خواہ کتنی ادنیٰ ہوں، تیری بے کسی خواہ کس قدر ظاہر ہو، بے شک دنیا نے تیرے اعمال کی قدر نہیں کی،اس کی نگاہ تیرے خیر کو دیکھنے سے قاصر رہی ہے مگر خدا تیرے عمل خیر کو دیکھ رہا ہے اور وہ ایک دن تجھ کو بھی اپنے ان کاموں کے نتائج دکھا دے گا.دوسری طرف یہ آیت عمل شر کرنے والوں کو تنبیہ کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے اے شریر انسان ! تو جوچوری چھپے شرار تیں کرتا ہے تجھے چوروں میں بھی عظمت حاصل نہیں تجھے ڈاکوئوں میں بھی عظمت حاصل نہیں اور تجھے شر کرتے ہوئے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا مگر ہم تجھے دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھ کو ان شرارتوں کا ایک دن پوری طرح مزہ چکھا دیں گے.غرض جزائے خیر و شر کے متعلق یہ ایک ایسا عظیم الشان اصل ہے کہ اگر اس کو پوری طرح سمجھ لیا جائے تو صحیح نیکی پیدا ہوتی اور بدی سے بچنے کا صحیح جذبہ انسانی قلب میں پیدا ہو جاتا ہے.بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ پھر تواس کا یہ نتیجہ نکلا کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ.جب ہر بدی کا بدلہ ضرور دیکھنا ہو گا تو پھر بخشش اور توبہ کے کیا معنے ہوئے.اور جب ہر خیر کا بدلہ ضرور دیکھنا ہوگا تو پھر دوزخ میں لوگ کیوں ڈالے جائیں گے.گویا ایک آیت وہ ہے جو جنت کی نفی کرتی ہے اور دوسری آیت وہ ہے جو دوزخ کی نفی کرتی ہے.مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.دوزخ کی نفی کر رہی ہے اور مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ جنت کی نفی
Page 105
کررہی ہے.پس یہ کیسی آیت ہوئی کہ دو دھاری تلوار بن کر اس نے جنت کو بھی اڑا دیا اور دوزخ کو بھی اڑا دیا.جنت کو بھی بےکار قرار دے دیا اور دوزخ کو بھی بےکار قرار دے دیا.اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ کوئی چیز ضائع نہیں جاتی.لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جس طرح دنیا میں حساب ہوتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کے قانون میں بھی حساب مقدر ہے.فرض کرو زید اور بکر دو آدمی ہیں اور زید کے بکر کے پاس ایک ہزار روپے ہیں لیکن زید کے ذمہ بکر کے دو ہزار روپے ہیں.اب یہ لازمی بات ہے کہ جب حساب ہوگا تو بکر اس سے صرف ایک ہزار روپیہ مزید لے کر اپنے گھر چلا جائے گا.ایسی صورت میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بکر کاہزار روپیہ ضائع گیا.بکر کا اس سے دو ہزار کی جگہ ہزار لے جانا ہی بتاتا ہے کہ اس کا ہزار ضائع نہیں گیا بلکہ کام آگیا کیونکہ بکر نے تو دو ہزار روپے لینے تھے مگر چونکہ زید کے ایک ہزار روپے اس کے پاس پہلے موجود تھے اس لئے دو ہزار میں سے ایک ہزار روپے وضع ہو گئے اور زید کو دوہزار کی بجائے صرف ایک ہزار روپیہ زائد دینا پڑا.یہی حال نیکیوں اور بدیوں کا ہے.اﷲ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ١ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ١ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ(ھود :۱۱۵) تم نمازیں قائم کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی اسی طرح رات کے دونوں کناروں میں یعنی ہر تغیر جو واقعہ ہو تا ہے اس میں تمہیں اﷲ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے.دن آئے تو تم عبادت کرو دن جانے لگے تو تم عبادت کرو.رات آئے تو تم عبادت کرو رات جانے لگے تو تم عبادت کرو.اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ دنیا میں ہرتبدیلی کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ جاتی ہے اور وہ تغیر اور تبدیلی یا تو خیر کا موجب ہوتی ہے یا شر کا موجب ہوتی ہے.اگر تم اﷲ تعالیٰ کی عبادت بجا لائو گے اور ہر تغیر کے وقت اﷲتعالیٰ کی طرف جھکو گے تو اگر وہ تغیر تمہارے لئے کسی شر کا موجب ہو گا تو عبادت کرنے سے وہ شر دور ہو جائے گا اور اگر کسی شر کا موجب نہیں ہو گا تو تمہارے اعمال خیر میں اضافہ ہوتا رہے گا دونوں طرح تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے.جب نیا دن آئے گا تو یا تمہارے لئے خیر لائے گا یا شر لائے گا اور جب دن جائے گا تو یا تمہارے لئے خیر چھوڑ جائے گا یا شر چھوڑ جائے گا.اسی طرح رات آئے گی تو یا تمہارے لئے خیر لائے گی یا شر لائے گی اور جب رات جائے گی تو یا تمہارے لئے خیر چھوڑ جائے گی یا شر چھوڑ جائے گی.اگر تم ہر تغیر کے وقت اﷲ تعالیٰ کی عبادت بجالائو گے تو تمہاری نمازیں اور تمہاری عبادتیں اور تمہاری دعائیں شر کو اڑا دیں گی.کیونکہ بہر حال رات اپنے آنے اور جانے کے وقت اسی طرح دن اپنے آنے اور جانے کے وقت یا خیر لائے گا یا شر لائے گا.یا خیر چھوڑ جائے گا یا شر چھوڑ جائے گا.اگر دن آتے اور جاتے تمہارے لئے شر چھوڑ گیا ہے اور تم نے نماز پڑھ لی ہے تو دن کا شر دورہو جائے گا اوراگر رات آتے اور جاتے تمہارے لئے شر چھوڑ گئی
Page 106
ہے اور تم نے نماز پڑھ لی ہے تو رات کا شر دور ہو جائے گا.اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ.اﷲ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ نیکی بدی کا ازالہ کر دیا کرتی ہے.اگر بدی ہو تو نیکی سے وہ فوراً کٹ جاتی ہے اور اگر خیر ہی خیر ہو تو پھر عبادت تمہاری نیکیوں کو اور بھی بڑھا دے گی.یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ ان نیکیوں کو شر کے ازالہ پر خرچ کیا جائے.بہر حال اﷲ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ جب تم سے کوئی شر ظاہر ہو یا کسی شر کا امکان تمہارے لئے پیدا ہو تو تم فوراً نیکی کر لیا کرو تاکہ بدی کٹ جائے اور تمہیں اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے.ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ یہ ایک گُر ہے جو ہم نے تمہیں بتا دیا ہے اگر تم اپنے پہلو کو ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو ہماری اس نصیحت کو یاد رکھو کہ دن اور رات کے آتے جاتے وقت ضرور عبادت کر لیا کرو.جب دن آئے گا تو یا تمہارے لئے خیر لائے گا یا شر لائے گا اسی طرح جب رات آئے گی تویا تمہارے لئے خیر لائے گی یا شر لائے گی.جب دن جائے گا تو یا تمہارے لئے خیر چھوڑ جائے گا یا شر چھوڑ جائے گا اور جب رات جائے گی تو وہ بھی تمہارے لئے یا خیر چھوڑ جائے گی یا شر چھوڑ جائے گی تم ہر تغیر کے وقت عبادت کر لیا کرو اگر دن اور رات کا آنا جانا تمہارے لیے خیر لائے گا تو تمہاری خیر دگنی ہو جائے گی اور اگر شر لائے گا تو عبادت سے وہ شر کٹ جائے گا اور تمہارا پہلو یقینی طور پر محفوظ ہو جائے گا.اسی طرح فر ما تاہے فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ.فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ.وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ.فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ.نَارٌ حَامِيَةٌ (القارعۃ:۷تا۱۲) جس کے وزن بھاری ہو جائیں گے (بھاری کا یہ مطلب ہے کہ بمقابلہ بدی کے اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی) اسے ہمارے قرب کا مقام حاصل ہو گا اور اس کی اُخروی حیات سنور جائے گی.وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ لیکن جس کے وزن ہلکے رہیں گے فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ.اُس کی ماں ہاویہ ہوگی.بدی کا کوئی وزن نہیں وزن صرف نیکی کا ہے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ وزن اصل میں نیکی کا ہی ہوتا ہے بدی کا نہیں ہوتا.اس مسئلہ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی لوگوں نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں.حقیقت یہ ہے کہ وزن والی چیز صرف نیکی ہی ہوتی ہے بدی کا کوئی وزن نہیں ہوتا.پس اَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ کا یہ مطلب ہے کہ جس کی بدیوں نے اس کی نیکیوں کو کاٹ نہیں دیا اور اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ کا یہ مطلب ہے کہ جس کا وزن گھٹ گیا یعنی نیکیاں باقی نہ رہیںفَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وہ دوزخ میں گرایا جائے گا.پھر فرمایا وَ الْوَزْنُ يَوْمَىِٕذِ ا۟لْحَقُّ١ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ(الاعراف:۹،۱۰) اس دن وزن کا ہونا ایک قطعی اور
Page 107
یقینی بات ہے.جس کے وزن بھاری ہو جائیں گے یعنی بدیاں اڑجائیں گی اور نیکیاں باقی رہ جائیں گی وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس کے وزن ہلکے ہو جائیں گے اور وزن کے ہلکا ہونے کے یہ معنے ہیں کہ اس کی بدیاں زیادہ ہو ں گی.نیکیاں ان بدیوں کو اڑا نے کے لئے انسان کے پاس نہیں ہوں گی.فَاُولٰٓىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان پانے والے ہوں گے بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ کیونکہ یہ لوگ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے.اس سوال کا جواب کہ جب ہر بدی کا بدلہ ملتا ہے تو توبہ کے کیا معنی ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ یہ خیال کہ جب ہر بدی کا بدلہ انسان نے ضرور دیکھنا ہے تو پھر بخشش اورتوبہ کے کیا معنے ہوئے اور جب ہر خیر کا بدلہ انسان نے ضرور دیکھنا ہے تو پھر دوزخ کا کیا فائدہ ہوا بالکل غلط ہے ہر انسان نے جو عمل خیر کیا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن موجود ہوگا اور جو اس نے عمل شر کیا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن موجود ہو گا.وہ اپنے خیر کو بھی دیکھے گا اور اپنے شر کو بھی دیکھے گا اور دونوں کے تقابل کے نتیجہ میں جو چیز زیادہ ہو گی وہ دوسرے حصہ کو کاٹ دے گی.خیر زیادہ ہو گا تو اس کی وجہ سے شر کٹ جائے گا اور اگر شر زیادہ ہو گا تو خیر کٹ جائے گا بہر حال چھوٹا حساب بڑے حساب میں سے وضع کر لیا جائے گا مثلاً ایک شخص ایسا ہے جس نے دس ہزار نیکی کی اورایک ہزار بدی.ایک اور شخص ایسا ہے جس نے دس ہزار نیکی کی اور پانچ سو بدی کی.ایک اور شخص ایسا ہے جس نے دس ہزار نیکی کی اور دو سو بدی کی.ایک اور شخص ایسا ہے جس نے دس ہزار نیکی کی مگر بدی کوئی ایک بھی نہیں کی تو لازماً وہ شخص جس نے کوئی بدی نہیں کی وہ اونچے درجہ پر ہوگا اس سے نیچے وہ شخص ہوگا جس نے دوسو بدیاں کیں.اس سے نیچے وہ شخص ہوگا جس نے پانچ سو بدیاں کیں.اس سے نیچے وہ شخص ہوگا جس نے ایک ہزار بدیاںکیں.بے شک یہ سب لوگ جنت میں ہوں گے مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سب نے اپنے شر کو دیکھ لیا.اس نے بھی دیکھ لیا جس نے ایک ہزار بدیاں کی تھیں کیونکہ اسے وہ مقام نہ ملا جو پانچ سو بدیاں کرنے والے کو ملا اور اس نے بھی شر دیکھ لیا جس نے پانچ سو بدیاں کی تھیں کیونکہ اسے وہ مقام نہ ملا جو دوسو بدیاں کرنے والے کو ملا.اور اس نے بھی شر دیکھ لیا جس نے دو سو بدیاں کی تھیں کیونکہ اسے وہ مقام نہ ملا جو اس شخص کو ملا جس نے کوئی بدی بھی نہیں کی تھی.آخر یہ واضح بات ہے کہ کیوں محمد رسول اﷲ صلی اللہ علیہ وسلم محمدیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے.ابو بکرؓ کیوں ابوبکر ؓ کے مقام پر ہو گا.عمرؓ کیوں عمر ؓ کے مقام پر ہو گا اور عام مومن کیوں عام مومنوں کے مقام پر ہوں گے.اسی لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدی نہیں کی.اس لئے آپ کو اﷲ تعالیٰ کے قرب کا انتہائی مقام مل گیا.ابو بکر ؓ سے کچھ غلطیاں ہوئیں اس لئے انہیں وہ مقام نہ ملا جو محمد رسول اﷲ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا.پس ابو بکر ؓ نے اپنے شر کو دیکھ
Page 108
لیا.اس کے بعد عمر ؓ کو ابو بکر ؓ کا مقام بھی نہ ملا پس عمرؓ نے بھی اپنے شر کو دیکھ لیا اسی طرح ہر مومن جو جنت میں گیا جب اسے ابو بکر ؓ اور عمر ؓ کا مقام نہ ملا تو اس نے بھی اپنا شر دیکھ لیا.کیونکہ جس قدر کسی کے اعمال میں شر کا دخل ہوتا ہے اسی قدر اس کے اعمال خیر میں کٹوتی ہو جاتی ہے اور یہی شر کو دیکھنے کا مفہوم ہے.عیسائی لوگ بڑی ہنسی اڑا یا کرتے ہیں کہ اسلام کا خدابہی کھاتے والا خدا ہے حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کے بغیر امن قائم ہی نہیں ہو سکتا.خود عیسائیوں سے اگر پوچھا جائے کہ جس مقام پر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہو کیا اسی مقام پرقیامت کے دن تمام مومن ہوں گے تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ اﷲ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مقام پر رکھے گا اور مومنوں کو اور مقام پر.اور جب خود ان کا یہ اعتقاد ہے تو وہ اسلام پر کس منہ سے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اسلام کا خدا بہی کھاتے والا خدا ہے.اسی طرح فرماتا ہے مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا١ۚ وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (الانعام:۱۶۱) جو شخص نیک عمل کرے گا اسے اس کے عمل کی قیمت سے دس گنے زیادہ اجر ملے گا اور جو بد عمل کرے گا اسے اس کے عمل سے زیادہ کسی صورت میں بھی سزا نہیں ملے گی اور یقیناً ہماری طرف سے بدوں پر بھی کسی قسم کا ظلم روا نہیں رکھا جائے گا.اس آیت نے اس خطرہ کو دور کر دیا جو مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ کی وجہ سے ہر مومن کو محسوس ہوتا تھا کہ جب ایک چھوٹی سے چھوٹی بدی کا انجام بھی مجھے دیکھنا پڑے گا تو میری مغفرت کی کیا صورت ہو گی.اﷲ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ نیکی بڑھتی ہے اور اس کا دس گنے اجر دیا جاتا ہے لیکن بدی کے متعلق ہمارا یہ قانون ہے کہ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا.اس کا اس کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اسے دس بیس گنا بڑھا دیا جائے اس لئے اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تمہیں اپنے شر کا برا انجام نہ دیکھنا پڑے تو ہم تمہیں یہ علاج بتاتے ہیں کہ تم نیکی کا بیج بودو.نیکی کا بیج ہمارے قانون کے مطابق بڑھے گا اور ترقی کرے گا یہاں تک کہ تمہاری ایک ایک خیر دس دس نیکیوں کی شکل اختیار کرے گی لیکن بدی کا بیج پنپ نہیں سکتا.اس لئے نیکیوں کے غلبہ کی وجہ سے اﷲ تعالیٰ تمہاری مغفرت کے سامان پید افرما دے گا.خیر اور شر کی مثال اچھے اور گندے بیج کی در حقیقت قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر اور شر کی مثال ایک اچھے اور گندے بیج کی سی ہے.اچھا بیج پھل پیدا کرتا ہے لیکن سڑا ہوا بیج کوئی پھل پیدا نہیں کرتا اگر تم زمین میں کوئی سڑا ہوا بیج بودو تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے نتیجہ میں ایک اور سڑا ہوا بیج پید اہو جائے.لیکن اگر تم اچھا بیج بو دو تو ایک دانے سے کئی کئی سو دانے پیدا ہو جاتے ہیں.اسی طرح بدی چونکہ سڑی ہوئی چیز ہے وہ اپنی ذات تک محدود
Page 109
رہتی ہے اور جس طرح سڑی ہوئی گٹھلی سے کوئی پودہ نہیں اُگ سکتا.آم کی سڑی ہوئی گٹھلی بو دو تو اس سے سڑے ہوئے آم پیدا نہیں ہوں گے لیکن آم کی اچھی گٹھلی بو دو تو اچھے آم پیدا ہونے لگیں گے.اسی طرح نیکی ترقی کرتی ہے لیکن بدی اپنی ذات تک محدود رہتی ہے.اگر تم چاہتے ہوکہ بدیاں تمہاری نجات کی راہ میں حائل نہ ہوں تو تمہیں ہماری نصیحت یہ ہے کہ تم کثرت سے نیکیاں بجا لائو.پھر فرماتا ہے وَ هُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ(الشورٰی :۲۶) وہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا، ان کی کو تا ہیوں سے درگذر کرتا اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں.پھر فرماتا ہے وَ مَاۤ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ (الشورٰی:۳۱) تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ اپنے اعمال کے نتیجہ میں پہنچتی ہے اور اﷲ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ انسان کے اکثر گناہوں سے چشم پوشی کرتا ہے.ان آیات سے وہ اعتراض باطل ہو گیا جو بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہر نیکی کا بدلہ ملنا ہے اور ہربدی کی سزا مقدر ہے تو پھر جنت اور دوزخ کے کیا معنے ہوئے.اگر ہر خیر کا بدلہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے تو پھر دوزخ اڑ گئی اور اگر ہر بدی کا بدلہ ہم نے ضرور دیکھنا ہے تو پھر جنت اڑ گئی.اوپر کی بیان کردہ آیات نے اس اعتراض کا باطل ہونا ثابت کر دیا ہے اور بتادیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہر نیکی قابل جزا ہے اور ہر بدی قابل پاداش پھر بھی جنت اپنی جگہ قائم رہے گی اور دوزخ اپنی جگہ قائم رہے گی جس کی بدیاں زیادہ ہوں گی وہ دوزخ میں گر ا یا جائے گا اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا جس کی بدیوں کی کثرت اس کی نیکیوں کو کھا جائے گی وہ دوزخ میں چلا جائے گا اور جس کی نیکیوں کی کثرت اس کی بدیوں کو کھا جائے گی وہ جنت میں چلا جائے گا.غرض جنت بھی قائم رہی اور دوزخ بھی.اسی طرح احادیث میں آتا ہے ابن جریر حضرت انس ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ کَانَ اَبُوْ بَکْرٍ یَأْکُلُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَ سَلَّمَ فَنَزَلَتْ ھٰذِہِ الْاٰیَۃُ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.حضرت ابو بکر ؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص ایک ذرّہ بھر بھی نیکی کرے گا وہ اس کا انجام دیکھ لے گا اور جو شخص ایک ذرّہ بھر بھی بدی کرے گا وہ اس کا انجام دیکھ لے گا فَرَفَعَ اَبُوْ بَکْرٍ یَدَہٗ.حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیت سن کر گھبرا گئے اور انہوں نے کھانے سے اپنا ہاتھ اٹھا
Page 110
لیا وَقَالَ یَا رَسُوْ لَ اللہِ اِنّیْ اُجْزٰی بِـمَا عَـمِلْتُ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّۃٍ مِّنْ شَـرٍّ اور کہا یا رسول اﷲ کیا ایک ذرّہ بھر بدی مجھ سے سرزد ہوئی تو قیامت کے دن مجھے اس کی سزا ملے گی اگر ایسا ہوا تب تو بڑی مشکل ہے.فَقَالَ یَا اَبَا بَکْرٍ مَارَأَیْتَ فِی الدُّنْیَا مِـمَّا تَکْرَہُ فَبِمَثَاقِیْلِ ذَرِّ الشَّـرِّ وَ یَدَّخِرُاللہُ لَکَ مَثَاقِیْلَ الْـخَیْرِ حَتّٰی تُوَفّٰی یَوْمَ الْقِیَامَۃَ (تفسیر طبری سورۃ الزلزال زیر آیت اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا).رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے مگر اے ابو بکر تم گھبرائو نہیں دنیا میں انسان کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ذرہ ٔشر کی وجہ سے پہنچتی ہیں اس طرح خدا تعالیٰ شر کے ذروں کو یہیں ختم کر دے گا اور خیر کے ذروں کو باقی رکھے گا اور انہی کی بنا پر مومن کو جنت میں داخل کیا جائے گا.اس حدیث کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہر ایک کے لئے نہیں بلکہ ابو بکر ؓ یا ابو بکر ؓ جیسے مقام کے انسان کے لئے ہے.حضرت ابو بکر ؓ کی اتنی ہی بدیاں تھیں جو دنیا میں ختم ہو سکتی تھیں اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں.تمہارا شر اتنا ہی ہے کہ اگر تمہیں کبھی بخار چڑھا یا روپیہ ضائع ہو گیا یا کوئی اورتکلیف پہنچی تو اسی میں وہ ذرہ شر ختم ہو جائے گا اور قیامت کے دن تمہارے اعمال میں خیر ہی خیر ہو گا.اسی طرح ابن جریر ہی حضرت عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں اِنَّہٗ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَھَا وَ اَبُوْبَکْرٍ الصِّدِّیْقُ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ قَاعِدٌ فَبَکٰی حِیْنَ اُنْزِلِتْ یعنی جب یہ سورۃ نازل ہوئی کہ اِذَازُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَھَا تو اس وقت حضرت ابو بکر ؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے.آپ نے یہ سورۃ سنی تو رو پڑے.فَقَالَ لَہٗ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَا یُبْکِیْکَ یَا اَبَا بَکْرٍ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو بکر تمہیں کس بات نے رُلا یا ہے ؟ قَالَ یُبْکِیْنِیْ ھٰذِہِ السُّوْرَۃُ.حضرت ابوبکرؓ نے کہا یارسول اﷲ مجھے تو اس سورۃ نے رُلایا ہے یعنی اگر ہم نے شر کا ایک ذرّہ بھی دیکھنا ہے تب تو ہم جنت سے محروم رہے فَقَالَ لَہٗ رَسُوْلُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَوْلَا اِنَّکُمْ تُـخْطِئُوْنَ وَتُذْنِبُوْنَ فَیَغْفِرُ لَکُمْ لَـخَلَقَ اللہُ اُمَّۃً یُـخْطِئُوْنَ وَیُذْنِبُوْنَ فَیَغْفِرُ لَھُمْ(تفسیر طبری سورۃ الزلزال زیر آیتاِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرائو نہیں بےشک مومن شر بھی دیکھیں گے مگر شر دیکھنے سے مراد ان کا اپنے گناہوں سے توبہ کرناہے جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یہی اس کا شر کو دیکھنا ہو جاتا ہے کیونکہ توبہ اسی وقت کی جاتی ہے جب انسان کا دل ندامت سے پُر ہو جائے اور وہ اپنے گذشتہ گناہوں کو یاد کرکے سخت شرمندہ ہو اور محسوس کرے کہ اس نے اپنی زندگی میں بڑی بھاری غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے جن کی اسے تلافی کرنی چاہیے.
Page 111
پس چونکہ توبہ کے وقت انسان کا دل زخمی ہو تا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے سخت شرم سار ہوتا ہے اس لئے یہی اس کا اپنے شر کو دیکھنا ہو تا ہے.اگر وہ شر نہ کرتا تو اس کے دل کو اس رنگ میں تکلیف بھی نہ پہنچتی.اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا ہی اس رنگ میں کیا ہے کہ اس نے ان میں صفت قدرت رکھ دی ہے یعنی وہ بدی بھی کر سکتے ہیں اور نیکی بھی کر سکتے ہیں.اگر کوئی صاحب قدرت مخلوق نہ ہوتی تو اﷲ تعالیٰ کی بعض صفات دنیا پر ظاہر نہ ہو سکتیں.صاحب قدرت مخلوق ہو نے کی وجہ سے چونکہ لوگوں سے بدیاں بھی سر زد ہو تی ہیں اور نیکیاں بھی اس لئے اس کی کئی صفات ظاہر ہوتی رہتی ہیں کہیں غفاری کی صفت ظاہر ہورہی ہے، کہیںستاری کی صفت ظاہر ہورہی ہے،کہیں رزاقیت کی صفت ظاہر ہو رہی ہے،کہیں امانت کی صفت ظاہر ہو رہی ہے،کہیں احیاء کی صفت ظاہر ہو رہی ہے اور یہ سب صفات وہ ہیں جو انسانی پیدائش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرو اورخدا تعالیٰ تمہاری توبہ پر مغفرت سے کام نہ لے تو لَـخَلَقَ اللہُ اُمَّۃً یُـخْطِئُوْنَ وَیُذْنِبُوْنَ فَیَغْفِرُ لَھُمْ اﷲ تعالیٰ یقیناً اورلوگ ایسے پیدا کر دے جو گناہ کریں اور اﷲ تعالیٰ ان کو معاف کرے.اس کے یہ معنے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو گناہ پسندہیں بلکہ یہ کہ صاحب قدرت مخلوق ہی صفات الٰہیہ کو ظاہر کرتی ہے.اگر صاحب قدرت مخلوق دنیا میں نہ ہوتی تو اس کی بعض صفات بھی ظاہر نہ ہوتیں اور جب انسان کو صاحب قدرت بنایا گیا ہے تو بہر حال صاحب قدرت مخلوق میں سے کچھ گناہ گار بھی ضرور ہوں گے.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہوں تو صاحب قدرت مگر ہر شخص نیکی پر مجبور ہو.انسان کا صاحب قدرت ہونا ہی بتا رہا ہے کہ انسا نوں میں سے کچھ بدیوں کا بھی ارتکاب کریں گے اور پھر ان میں سے جو چاہیں گے ان کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا تا اگر ان کا دل شرمندہ ہو اور ندامت کی آگ میں جل کر صاف ہو جائے تو توبہ کے ذریعہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس طرح اﷲ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوتی رہیں.اسی طرح ابن ابی حاتم ابی سعید الخدری سے روایت کرتے ہیں کہ قَا لَ لَمَّا اُنْزِ لَتْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ قُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللہِ اِنِّیْ لَرَاءٍ عَـمَلِیْ قَالَ نَعَمْ.یعنی ابو سعید خدری کہتے ہیںکہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اﷲکیا میں اپنے ہر عمل کا نتیجہ دیکھوں گا ؟ آپ نے فرمایا ہاں.قُلْتُ تِلْکَ الْکِبَارُ الْکِبَارُ میں نے کہا بڑے بڑے عمل بھی نظر آئیں گے؟ قالَ نَعَمْ فرمایا ہاں قُلْتُ تِلْکَ الصِّغَارُ الصِّغَارُ.میں نے کہا چھوٹے چھوٹے عمل بھی نظر آئیں گے؟قَا لَ نَعَمْ.آپ نے فرمایا
Page 112
اسی طرح ابن ابی حاتم ابی سعید الخدری سے روایت کرتے ہیں کہ قَا لَ لَمَّا اُنْزِ لَتْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ قُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللہِ اِنِّیْ لَرَاءٍ عَـمَلِیْ قَالَ نَعَمْ.یعنی ابو سعید خدری کہتے ہیںکہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اﷲکیا میں اپنے ہر عمل کا نتیجہ دیکھوں گا ؟ آپ نے فرمایا ہاں.قُلْتُ تِلْکَ الْکِبَارُ الْکِبَارُ میں نے کہا بڑے بڑے عمل بھی نظر آئیں گے؟ قالَ نَعَمْ فرمایا ہاں قُلْتُ تِلْکَ الصِّغَارُ الصِّغَارُ.میں نے کہا چھوٹے چھوٹے عمل بھی نظر آئیں گے؟قَا لَ نَعَمْ.آپ نے فرمایا ہاں.قُلْتُ وَاثْکُلَ اُمّیْ.میں نے کہا میری ماں مجھ کو روئے پھر تو میں مرا.قَالَ اَ.بْشِـرْ یَا اَبَا سَعِیْدٍ فَاِنَّ الْـحَسَنَۃَ بِعَشْـرِ اَمَثَالِہَا یَعْنِی اِلٰی سَبْعِ مِائَۃِ ضِعْفٍ وَّیُضْعِفُ اللہُ لِمَنْ یَّشَآءُ.آپ نے فرمایا اے ابو سعید یہ آیت گھبراہٹ پیدا کرنے والی نہیں یہ تو نیکی اور بدی کی جزا کے متعلق اﷲ تعالیٰ کے قانون کو بیان کرتی ہے.کافر بے شک گھبرا سکتا ہے لیکن مومن کے لئے گھبرا نے کی کوئی وجہ نہیں.کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نیکی کا دس گنے اجر ملے گا.پس یہ جو اﷲ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کا ایک ذرہ بھی کرے گا وہ اسے دیکھے گا.اس میں خیر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کی ایک نیکی ہوگی اسے دس گنا بڑا کر کے دکھایا جائے گا یعنی جو شخص کوئی ایک نیکی بجا لائے گا خدا تعالیٰ کے حضور اس کی دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور پھر ان دس نیکیوں کو سات گنا کیا جائے گا.گویا ایک نیکی کا اجر ستر گنے تک پہنچا دیا جائے گا اور اﷲ تعالیٰ جسے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بدلہ دے گا.وَالسَّیِّئَۃُ بِـمِثْلِھَا اَوْیَغْفِرُ اللہُ.لیکن اگر کسی نے کوئی بدی کی ہوگی تو اس کا بدلہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس سے قصور سر زد ہوا ہوگا یا اﷲ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا.یعنی نیکی کے متعلق اﷲ تعالیٰ کا جو قاعدہ ہے وہ بدی کے متعلق نہیں.پس مومن کے لئے گھبراہٹ کا کوئی مقام نہیں ہاں اگر کافر گھبرائے تو وہ اس کا سزا وار ہے.پھر آپ نے فرمایا وَلَنْ یَنْجُوَ اَحَدٌ مِّنْکُمْ بِعَمَلِہِ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے عمل کے زور سے نجات حاصل کر سکے.نجات کا موجب عمل نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے.قُلْتُ وَلَا اَنْتَ یَا رَسُوْلَ اللہِ.میں نے کہا یا رسول اﷲ کیا آپ بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پائیں گے؟ قَالَ وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ یَّتَغَمَّدَنِیَ اللہُ مِنْہُ بِرَحْـمَۃٍ (تفسیر الدر المنثور سورۃ الزلزال زیر آیت اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا).آپ نے فرمایا نہیں میں بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پاسکتا میری مغفرت بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اﷲتعالیٰ اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ لے.درحقیقت اگر ہم غور کریں تو بات وہی ہے جو غالب نے کہی کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر نبی نیکی کرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے ہی کرتا ہے.پس منطقی طور پر اگر دیکھا جائے تو نبی کے ہاتھ میں بھی سوائے فضل کے اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اگر اس نے نماز پڑھی ہے یا روزہ رکھا ہے یا حج کیا ہے یا صدقہ و خیرات میں حصہ لیا ہے یا اور نیکیاں کی ہیں تو وہ سب کی سب خدا تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں سے کی ہیں اس لئے خالص منطقی نظریہ سے اگر دیکھا جائے تو نبی کی نجات بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی.بے شک
Page 113
عملی نظریہ میں ایک شخص نیک ہوتا ہے اورایک بد.لیکن منطقی نظریہ کے ماتحت کوئی بڑے سے بڑا نیک بھی محض اعمال کی بنا پر نجات کا مستحق نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ اس نے جو کچھ کیا اﷲ تعالیٰ کی طاقتوں سے کام لے کر کیا ہے.اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے خالص منطقی نظریہ کے ماتحت فرمایا ہے عملی نظریہ کے ماتحت نہیں.اسی طرح ابن ابی حاتم سعید بن جبیر سے اﷲ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق کہ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کس واقعہ پر نازل ہوئی تھی.میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ روایات میں کسی آیت کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے اس کے صرف اتنے معنے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی فلاں آیت پر چسپاں ہوتا ہے.یہ معنے نہیں ہوتے کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو آیت کا نزول بھی نہ ہوتا.بہر حال سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا (الدّھر:۹)وہ لوگ اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس وقت صحابہ ؓ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہمیں اﷲ تعالیٰ کی راہ میں تھوڑی سے چیز دینے پر کیا اجر مل سکتا ہے اجر تو اسی خیر پر ملے گا جو بہت بڑی ہو گی.ضمناً میں یہ بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا کے کئی معنے ہو سکتے ہیں.عَلٰى حُبِّهٖ کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ عَلٰی حُبِّ الطَّعَامِ یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ عَلٰی حُبِّ اِطْعَامِ الطَّعَامِ.اور یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ عَلیٰ حُبِّ اللہِ یعنی اس آیت میں تین درجے بیان کئے گئے ہیں اور بتاتا گیا ہے کہ مومن مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں.عَلٰی حُبِّ الطَّعَامِ با وجود ما ل کی محبت یا طعام کی محبت کے یعنی باوجود اس کے کہ انہیں خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی وہ غرباء و مساکین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے اور اپنی ضروریات کو پسِ پشت ڈال کر ان کو کھانا کھلانا مقدم سمجھتے ہیں.دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلٰی حُبِّ اِطْعَامِ الطَّعَامِ جبکہ انہیں کھانا کھلانے سے محبت ہوتی ہے یعنی ان کی طبیعت میں صدقہ و خیرات دینا اس قدر گہرے طور پر داخل ہوچکا ہوتا ہے کہ انہیں اس وقت تک چین اور آرام ہی نہیں آتا جب تک وہ دوسروں کو کھانا نہ کھلا لیں.تیسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ یُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّ اللہِ وہ محض اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے کھانا کھلاتے ہیں.ان کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی تعریف کریں یا جن کو کھانا کھلایا گیا ہے ان سے کوئی فائدہ حاصل کریں یا انہیں کوئی ثواب ملے بلکہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو مدّ ِنظر رکھتے ہیں.اس آیت میں صدقہ کے
Page 114
تین درجے بیان کئے گئے ہیں.پہلا یہ کہ انسان ایسی حالت میں صدقہ کرے جبکہ وہ خود ضرورت مند ہو.اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان کو صدقہ سے ایسا لگاؤ پیدا ہوجائے کہ جب تک وہ صدقہ نہ کر لے اسے چین اور آرام ہی نہ آئے اور پھر اس سے بڑا درجہ یہ ہےکہ یہ کام کسی بدلہ کی خواہش کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسانات کے شکریہ میں یہ کام کیا جائے.صحابہؓ نے اس کے معنے عَلٰی حُبِّ الطَّعَامِ کے ہی کئے ہیں یعنی ایسی چیز جو تم کو پسند بھی ہو اور تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والی بھی ہو وہ چیز تمہیں صدقہ میں دینی چاہیے.بہرحال سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہؓ نے اس کے یہ معنے کئے کہ قرآن کریم یہ ہدایت دیتا ہے کہ مساکین و یتامیٰ اور اسیروں کو ہمیں ایسا کھانا کھلانا چاہیے جو ہمیں مرغوب بھی ہو اور ہماری ضرورت کو بھی پورا کرنے والا ہو تو کَانَ الْمُسْلِمُوْنَ یَرَوْنَ اَنَّـھُمْ لَا یُؤْجَرُوْنَ عَلَی الشَّیْءِ الْقَلِیْلِ اِذَا اَعْطَوْہُ.اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اگر ہم کوئی تھوڑی سی چیز صدقہ دیں گے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا فَیَجِیْءُ الْمِسْکِیْنُ اِلٰی اَبْوَابِـھِمْ فَیَسْتَقِلُّوْنَ اَنْ یُّعْطَوْہُ تَـمْرَۃً وَالْکِسْـرَۃَ وَالْـجَوْزَۃَ وَ نَـحْوَ ذَالِکَ فَیَرُدُّوْنَہٗ وَ یَقُوْلُوْنَ مَا ھٰذَا بِشَیْءٍ اِنَّـمَا نُؤْجَرُ عَلٰی مَا نُعْطِیْ وَ نَـحْنُ نُـحِبُّہٗ.چنانچہ جب کوئی مسکین ان کے دروازہ پر آتا تو چونکہ ان کی مالی حالت ایسی نہیں ہوتی تھی کہ وہ زیادہ صدقہ دے سکیں اور دوسری طرف ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے کوئی تھوڑی سی چیز صدقہ میں دے دی تو ہمیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا اجر اسی چیز کا مل سکتا ہے جو زیادہ ہو اور ایسی حالت میں صدقہ دی جائے جب انسان اس کی خود ضرورت محسوس کرتا ہو.اس لئے وہ ایک آدھ کھجور یا روٹی کا ایک ٹکڑہ یا اخروٹ کا ایک دانہ اسے نہ دیتے اور کہتے جاؤ میاں ہمارے پاس کچھ نہیں وَ یَقُوْلُوْنَ مَا ھٰذَا بِشَیْءٍ.اور سمجھتے کہ ہم نے یہ کیا خیرات کرنی ہے اِنَّـمَا نُؤْجَرُ عَلٰی مَا نُعْطِیْ وَ نَـحْنُ نُـحِبُّہٗ.ہمیں تو اسی چیز کا بدلہ ملے گا جو ہم ایسی حالت میں دیں گے جبکہ ہمیں خود اس کی ضرورت ہوگی اور وہ بڑی ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا.وَکَانَ اٰخَرُوْنَ یَرَوْنَ اَنَّـھُمْ لَا یُلَامُوْنَ عَلَی الذَّنْبِ الْیَسِیْرِ الْکَذْبَۃِ وَالنَّظْرَۃِ وَالْغِیْبَۃِ وَاَشْبَاہِ ذَالِکَ.پھر بعض لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں پر کوئی سزا نہیں ملے گی جیسے کبھی جھوٹ بول لیا یا کسی غیر عورت پر نظر ڈال لی یا غیبت سرزد ہوگئی یا اسی قسم کا کوئی اور فعل ہوگیا تو ہمیں سزا نہیں ملے گی یَقُوْلُوْنَ اِنَّـمَا وَعَدَ اللہُ النَّارَ عَلَی الْکَبَائِرِ.وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کبائر پر سزا مقرر کی ہے صغائر پر نہیں فَرَغَّبَـھُمْ فِی الْقَلِیْلِ مِنَ الْـخَیْرِ اَنْ یَّعْمَلُوْہُ فَاِنَّہٗ یُوْشِکُ اَنْ یَّکْثُرَ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
Page 115
تحریک کرنی شروع کی کہ اگر تمہیں کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کا بھی موقع ملے تو وہ تمہیں ضرور کر لینی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ نیکی بڑھتی ہے اگر تم نیکی کا بیج بو دو گے تو خواہ وہ بظاہر کیسا ہی حقیر اور معمولی دکھائی دے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا اور جب قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر ملے گا تو تم اس کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے اس لئے کسی نیکی کو ضائع مت کرو.فَنَزَلَتْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ یعنی وَزْنَ اَصْغَرِ النَّمْلِ خَیْرًا یَّرَہٗ.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.جہاں تک اس آیت کے مفہوم کا سوال ہے اس حد تک تو مجھے راوی سے اتفاق ہے لیکن جہاں تک صحابہؓ کےساتھ اس آیت کا تعلق بیان کیا گیا ہے میں اس راوی کی رائے کا قائل نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اس میں صحابہؓ کی سخت ہتک کی گئی ہے کیونکہ ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں جنت ملے تب تو ہم کسی غریب کو کھلا سکتے ہیں لیکن اگر جنت نہ ملے تو ہم نہیں کھلا سکتے.یہ خیال ایسا ہے جو صحابہؓ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک لمحہ کے لئے بھی قابل قبول نہیں سمجھا جاسکتا.صحابہؓ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے اور ان کی حالت ہی بالکل بدل چکی تھی ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں کئی دہریہ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں لیکن اگر کوئی غریب ان کے پاس آجائے تو وہ اس کی مدد کے لئے فوراً تیار ہو جاتے ہیں.پس یہ بات کہ صحابہؓ نے مساکین کو روٹی کا ایک ٹکڑہ تک دینا ترک کر دیا تھا اور جب کوئی مسکین ان کے دروازہ پر آتا تو وہ اسے واپس لوٹا دیتے اور کہتے کہ جاؤ میاں ہمارے پاس کچھ نہیں قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد امر ہے.معلوم ہوتا ہے راوی نے خود بخود یہ خیال کر لیا ہے کہ صحابہؓ اس طرح کرتے ہوں گے.ورنہ صحابہؓ کی ذات اس اتہام سے بالکل بری ہے صحابہؓ کی شان تو بہت بلند ہے وہ لوگ جو کسی نیکی کی جزا کے قائل نہیں ہوتے، جو خدا تعالیٰ کی ہستی کو بھی تسلیم نہیں کرتے، جو دن رات دنیوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور جن کے سامنے اگر عقبیٰ کا ذکر کیا جائے تو ہنسی اڑانے لگتے ہیں وہ بھی بغیر اس بات کو سوچنے کے کہ ان کے فعل کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں غریبوں کی مدد کرتے چلے جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو ہزاروں روپیہ اس غرض کے لئے صرف کر دیتے ہیں.جب ایمان سے کلّی طور پر محروم لوگ بھی مساکین کو کھانا کھلاتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ انہیں اس کام کی کوئی جزا ملے گی یا نہیں تو صحابہؓ کے متعلق یہ کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو خیرات سے روک لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جب معمولی نیکی پر ہمارے لئے کوئی اجر مقرر نہیں تو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیوں کریں.پس یہ خیال جس کا صحابہؓ کے متعلق اظہار کیا گیا ہے بالکل غلط ہے.لیکن آیت کا جو مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے وہ درست ہے لکھتے ہیں مِثْقَالَ ذَرَّةٍ کے معنے یہ ہیں کہ
Page 116
وَزْنَ اَصْغَرِ النَّمْلِ خَیْرًا یَّرَہٗ جو شخص ایک چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا یعنی فِیْ کِتَابِہٖ وَیَسُـرُّہٗ ذَالِکَ وہ اسے خدا تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا پائے گا اور اسے دیکھ کر خوش ہوگا کیونکہ جس طرح اس نے نیکی کی ہوگی اسی طرح خدا تعالیٰ اس نیکی کے بدلہ میں اسے اپنے انعامات سے حصہ عطا فرمائے گا اور اسے اپنے فضلوں کا وارث کرے گا.اس کے بعد سعید بن جبیرؓ کہتے ہیں یُکْتَبُ لِکُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ بِکُلِّ سَیِّئَۃٍ سَیِّئَۃٌ وَّ بِکُلِّ حَسَنَۃٍ عَشْـرُحَسَنَاتٍ.ہرشخص جو نیک یا بد ہوگا اس کی نیکی بدی کی جزا کے متعلق اﷲ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے اس کی ایک بدی کے مقابلہ میں اﷲ تعالیٰ کے حضورصرف ایک ہی بدی لکھی جاتی ہے.لیکن جو شخص کوئی ایک نیکی بجا لاتا ہے اس کی ایک نیکی کے مقابلہ میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں.اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا چلا جاتا ہے.یعنی بدی کے نتیجہ میں صرف ایک بدی لکھی جاتی ہے اور نیکی کے نتیجہ میں ایک نہیں بلکہ دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں.فَاِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَۃِ جب قیامت کا دن آئے گا تو ضَاعَفَ اللہُ حَسَنَا تِ الْمُؤْمِنِیْنَ اَیْضًا بِکُلِّ وَاحِدَۃٍ عَشْـرًا اﷲ تعالیٰ مومنوں کی حسنات کو پھر بڑھائے گا اور ایک ایک نیکی کو دس گنا کرے گا.یعنی ایک دفعہ تو وہ پہلے بڑھا چکا ہوگا اور ایک ایک نیکی کو دس دس نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر چکا ہو گا لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر ان بڑھائی ہوئی نیکیوں میں سے ایک ایک دس گنا کرے گا.گویا ایک نیکی کی جزا سوگنے تک پہنچا دے گا.لوگوں نے تو دَہ در دنیا ستر در آخرت ایک محاورہ ایجاد کیا ہوا ہے لیکن اگر احادیث کے مفہوم کو ملحوظ رکھا جائے تو یہ محاورہ یوں بنتا ہے کہ دَہ در دنیا سو در آخرت وَیَـمْحُوْ عَنْہُ بِکُلِّ حَسَنَۃٍ عَشْـرَ سَیِّاٰتٍ.دوسری طرف اﷲ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کے بدلہ میں اس کی دس بدیوں کو دور کر دے گا.یعنی اگر اس نے ایک نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی دس بدیاں مٹا دے گا.دس نیکیاں کی ہوں گی تو سو بدیاں مٹا دے گا اور اگر سو نیکیاں کی ہوں گی تو ہزار بدیاں مٹا دے گا گویا دونوں رنگ میں اسے جزائے خیر عطا کی جائے گی.اس رنگ میں بھی کہ اس کی ایک ایک نیکی کو دس گنے اور پھر سو گنے تک بڑھا دیا جائے گا اوراس رنگ میں بھی اس کی ہر نیکی کے مقابلہ میں دس بدیوں کو مٹا دیا جائے گا.بات یہ ہے کہ اصل چیز محبت الٰہی ہے اور یہ رستہ شریعت نے اسی کے لئے تجویز کیا ہے جس کا دل اﷲ تعالیٰ کے عشق اور اس کی محبت سے لبریز ہوگا.اس کے لئے نہیں جس کا دل سخت ہو اور جواﷲ تعالیٰ کی محبت کا کوئی شمہ بھی اپنے قلب میں نہ رکھتا ہو اگر نیکی کرتا ہو تو وہ بھی اتفاقیہ طورپر
Page 117
اور اگر بدی سے بچتا ہو تو و ہ بھی اتفاقیہ طورپر.نہ اس کی نیکی کا باعث خدا تعالیٰ کی محبت ہو اور نہ اس کا بدی سے بچنا خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے ماتحت ہو.ایسا شخص اس انعام سے حصہ نہیں لے سکتا یہ انعام اسی کے لئے مقدر ہے جس کا دل اﷲ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو گا.اور جو اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود محبت الٰہی کی آگ اپنے اندر رکھتا ہو گا.اور یقیناً جس دل میں خدا تعالیٰ کی محبت ہو گی اسے کبھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا.اﷲ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح اس کی نجات کا سامان پید اکردے گا اور حساب بنا بنا کر اور مختلف ذرائع اور طریق اختیار کرکے اسے جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا.چنانچہ اسی روایت کا آخری حصہ یہ ہے کہ فَمَنْ زَادَتْ حَسَنَاتُہٗ عَلٰی سَیِّاٰتِہٖ مِثْقَالَ ذَرَّۃٍ دَخَلَ الْـجَنَّۃَ.اگر یہ تمام طریق اختیار کرنے کے بعد بھی کوئی شخص ایسا نکلا جس کی بدیوں سے اس کی نیکیاں صرف ایک ذرہ کے برابر بھی زیادہ ہوئیں تو اﷲ تعالیٰ اس کے متعلق اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ جائو اسے جنت میں داخل دو.اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو شخص سچا مومن ہو گا اور جس کے متعلق اﷲ تعالیٰ یہ جانتا ہو گا کہ اسے ایمان صادق حاصل ہے اس کو بچانے کے لئے اﷲ تعالیٰ ہر تدبیر اختیار کرے گا کہ وہ دوزخ میں نہ جائے جیسے ماں اپنے بچے کو مصیبت سے بچانے کے لئے اپنے سارے ذرائع صرف کر دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہؓ سے جو محبت تھی اور صحابہؓ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق پایا جاتا تھا وہ بھی اپنے اندربعض اس قسم کی مثالیں رکھتا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں سچی محبت ہو وہاں کوئی نہ کوئی ذریعہ دوسرے شخص کو مصیبت سے بچانے کے لئے نکال ہی لیا جاتا ہے.حدیثوں میں آتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اﷲ مجھ سے فلاں خطا سر زد ہو گئی ہے اب میں کیا کروں.آپ نے فرمایا کہ کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں غلام آزاد کرنے کی کہاں طاقت ہے.آپ نے فرمایا اچھا کیا تم د۲و مہینے متواتر روزے رکھ سکتے ہو ؟ اس نے عرض کیا یارسول اللہ روزے رکھنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں.آپ نے فرمایاتو پھر ساٹھ مسکینوںکوکھانا کھلا دو.کہنے لگا یا رسول اﷲ میں کہاں سے کھلائوں میرے پاس تو ان کو کھلانے کے لئے کچھ نہیں.ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ کوئی شخص کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایالو میاں یہ کھجوریں اٹھا ئو اور مساکین میں تقسیم کردو تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا.اس نے کھجوریں اٹھا لیں اور کہنے لگا یا رسول اﷲ ایک اور بات بھی عرض کرنے کے قابل ہے آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر تو اور کوئی غریب شخص نہیں.میں کسے تلاش کروں گا.آپ یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا جائو یہ کھجوریں خود ہی کھا لو.تمہاری طرف سے
Page 118
کفارہ ہو گیا(بخاری کتاب الصوم باب اذا جامع فی رمضان ).اسی طرح وہ شخص جو خدا تعالیٰ سے سچی محبت رکھتا ہو گا اور جس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش اور سعی اس بات کے لئے صرف کی ہوگی کہ اس کا انجام بخیر ہو اور وہ اﷲ تعالیٰ کے منعم علیہ گروہ میں شامل ہو جائے اگر کسی وجہ سے وہ اپنی اس کوشش میں سو فیصدی کامیاب نہ ہو سکا تب بھی اﷲ تعالیٰ اس کی تپش محبت کو رائیگاں جانے نہیں دے گا.بلکہ وہ اس کے ایمان اور اس کے دل کے اخلاص کے مطابق اس سے سلوک کرے گا اور کوئی نہ کوئی راہ اس کی نجات کی نکال لے گا اور اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جائو اور میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو.
Page 119
سُوْرَۃُ الْعٰدِیٰتِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ العادیات.یہ مکی سورۃ ہے وَھِیَ اِحْدٰی عَشْـرَۃَ اٰیَۃً دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم ا للہ کے سوا گیارہ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ عادیات مکی سورۃ ہے ابن مسعودؓ، جابر، الحسن،عکرمہ اور عطاء کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے.ابن عباسؓ، انسؓ، اور قتادہؓ کے نزدیک مدنی ہے (فتح البیان سورۃ العٰدِیٰتِ ابتدائیۃ).عبداللہ بن مسعودؓ چونکہ پرانے صحابی اور اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ میں سے ہیںاس لئے ان کی روایت عینی شہادت ہونے کی وجہ سے باقیوں سے زیادہ قابل قبول ہے.ابن عباس ؓ کی روایت کے (بوجہ اس کے کہ ابن عباسؓ مدینہ میں بالغ ہوئے ہیں مکی زندگی میں تو وہ دو تین سال کے تھے)صرف اتنے معنے سمجھے جائیں گے کہ انہوں نے مدینہ میں یہ سورۃ سنی.مگر اس سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ یہ سورۃ مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے کیونکہ جو سورۃ مکہ میں نازل ہو وہ مدینہ میں بھی سنی جاسکتی ہے.اسی طرح انسؓ (جو انصار میں سے تھے )کے قول کے بھی اتنے ہی معنے ہوں گے کہ انہوں نے یہ سورۃ مدینہ میں سنی ہے مگر جب عبداللہ بن مسعود ؓ کہتے ہوںکہ یہ سورۃ مکی ہے تو بوجہ اس کے کہ وہ مکہ میں ایمان والوںمیں سے ابتدائی لوگوں میں سے تھے اس کے معنے یہ ہیں کہ انہوں نے اس سورۃ کو مکہ میں سنا پس یہ روایت ان کے اَلسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ میں سے ہونے کی وجہ سے دوسری روایتوںسے زیادہ مقدم اور اہم ہے مستشرقین نے بھی بالخصوص ویری نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے.(A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry vol.4 P270) میں سمجھتا ہوں کہ ریورنڈویری کا خیال ادھر گیا ہی نہیںکہ اس کو مکی ثابت کرنے کے نتیجہ میںایک عظیم الشان پیشگوئی بن جائے گی.اگر یہ خیا ل انہیںآجاتا تو وہ کبھی اسے مکی قرار نہ دیتے کیونکہ ریورنڈ ویری کے لئے تو یہ بڑی مصیبت ہے کہ کسی پیشگوئی اور پھر عظیم الشان پیشگوئی کا قرآن کریم سے ثبوت ملتا ہو.اگر اس طرف ان کا ذہن جا تا تو وہ حسب عادت کہہ دیتے کہ گو اکثر رو ا یات اسے مکی قرار دیتی ہیںلیکن اس کا سٹائل مدنی ہے اس لئے روایتیں غلط ہیں.یہ ہے مدنی.
Page 120
ترتیب مضمون پارہ عَمَّ کی آخری سورتوں کی ترتیب یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی چند سورتوں سے (سوائے آخری ایک دو سورتوں کے)یہ طریق چلا آرہا تھا کہ ایک ہی سورۃ میںرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کا بھی ذکر کیا جاتا تھا اور بعثت ثانیہ کا بھی.مگر اب باری باری ایک ایک سورۃ میں ایک ایک زمانہ کا ذکر آتا ہے چنانچہ سورۃ البینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولیٰ کا ذکر کیا گیا تھا اور سورۃ الزلزال میں آپؐکی بعثت ثانیہ کا ذکر کیا گیا.یہ ایک عجیب فرق ہے جو ان آخری سورتوں میں پہلی سورتوں کے مقابل پر پیدا کر دیا گیا ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر میں سورتیں چھوٹی کر دی گئی ہیںتا کمزور حافظہ والے اور بچے بھی کچھ حصہ قرآن کریم کا آسانی سے یاد کر سکیں.پہلے چونکہ لمبی سورتیں تھیںاس لئے ایک ہی سورۃ میںدونوں زمانوں کا ذکر کر دیا جاتا تھا اب سورتیں چھوٹی ہو گئی ہیںاس لئے یہ طریق اختیار کر لیا گیا ہے کہ ایک سورۃ میں بعثت اولیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری سورۃ میں بعثت ثانیہ کا ذکر کیا جاتا ہے اسی ترتیب کے ماتحت زیر تفسیر سورۃمیں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی ترقیات کا ذکر کیا ہے اگلی سورۃ میںپھر آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر کیا جائے گا اور کچھ سورتوں تک یہی ترتیب چلتی چلی جائے گی اس کے بعد یہ ترتیب ایک نیا چکر کھائے گی اور پھر اس میں کچھ تبدیلی پیدا ہو جائے گی.بہرحال سورۃ الزلزال میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر تھا.سورۃ عادیات میں آنحضرتؐکی بعثت اولیٰ کا ذکر اس لئے سورۃ العادیات میںبعثت اولیٰ کا ذکر کیا گیا ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور)بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کر تا ہوں) وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًاۙ۰۰۲ (مجھے) قسم ہے جوش سے آوازیں نکالتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی.حلّ لُغات.عٰدِيٰت عَادِیَات: عَادِیَۃٌ سے جمع ہے جو عَدَا سے اسم فاعل کا مونث کا صیغہ ہے اور عَدَا ( یَعْدُوْ عَدْوًا وَ عَدَوَانًا وَ تَعْدَاءً وَعَدًا) الرَّجُلُ وَغَیْـرُہٗ کے معنے ہوتے ہیں جَرٰی وَ رَکَضَ کوئی شخص تیزی کے ساتھ دوڑا.اسی طرح( عَدْوًا وَ عُدْوَانًا) فُلَانًا عَنِ الْاَمْرِ کے معنے ہوتے ہیں صَـرَفَہٗ وَشَغَلَہٗ.کسی کو
Page 121
کام سے روک دیا.اور عَدَا عَلَیْہِ کے معنے ہوتے ہیں وَثَبَ کسی کے اوپر حملہ کیا یا جھپٹا مارا.اور عَدَا الْاَمْرَ یا عَدَا عَنِ الْاَمْرِ کے معنے ہوتے ہیں تَرَکَہٗ.اس کو چھوڑ دیا.اور عَدِیَ (یَعْدٰی عَدًا) لِفُلَانٍ کے معنے ہوتے ہیں اَبْغَضَہٗ.اس سے بغض رکھا(اقرب) ضَبْحًا ضَبْحًا: اَلضَّبْحُ نَوْعٌ مِّنَ الْعَدْوِ.مفردات میں لکھا ہے کہ ضَبْحٌ جانوروں کی دوڑوں میں سے ایک دوڑ کا نام ہے.اسی طرح لکھا ہے قِیْلَ الضَّبْحُ کَالضَّبْعِ وَ ھُوَ مَدُّ الضَّبْعِ فِی الْعَدْوِ.یعنی گھوڑے کا اگلے پائوں لمبے کر کے مارنا جس سے بغلوں میں فاصلہ ہوتا چلاجائے اس کو ضَبْحٌ کہتے ہیں.اور اقرب میں لکھا ہے اَلضَّبْحُ صَوْتٌ یُّسْمَعُ مِنْ صُدُوْرِ ا لْـخَیْلِ عِنْدَ الْعَدْوِ یعنی ضَبْحٌ اس آواز کو کہتے ہیںجو دوڑتے وقت گھوڑوں کے سینوں میں سے نکلتی ہے.یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد گھوڑوں کا ہنہنانا نہیں بلکہ دوڑتے وقت ان کے سینوں میں سے جو خاص قسم کی آواز نکلتی ہے اس کو ضَبْحٌ کہا جاتا ہے.لغت والوں نے لکھا ہے کہ یہ آواز اس قسم کی ہوتی ہے جس طرح اَہ اَہ کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں اسے ’’ہاہ ہاہ‘‘ کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیںجبکہ ’’ہا‘‘ کو گلا سکیڑ کر ادا کیا جائے.ان معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا کا ترجمہ یہ ہو گا کہ ۱.ہم ان دوڑنے والی سو ا ریوں کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیںجو ضَبْحٌ کی چال پر دوڑتی ہیں.ضَبْحٌ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ایک قسم کی تیز دوڑ کا نام ہے اور غالباً یہ کودنے والی دوڑ ہو گی جسے سر پٹ کہتے ہیںتبھی ان کے سینوں میں سے آواز پیدا ہوتی ہے.پس پہلے معنے یہ ہوں گے کہ ہم ان گھوڑوں کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیںجو دوڑتے وقت ضَبْحٌ چال اختیار کرتے ہیںیعنی شدت جوش سے کودتے جاتے ہیں.۲.دوسرے معنے یہ ہوں گے وہ دوڑنے والی سواریاںجو اگلے پائوں لمبے کر کے مارتی اور اچھل کر دوڑتی ہیں جس کے نتیجہ میںان کی بغلوں اور بازئووں میں لمبا فاصلہ ہوجاتا ہے ان کو ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.۳.تیسرے معنے یہ ہوں گے کہ ہم ان دوڑنے والی سواریوں کی قسم کھاتے ہیںجبکہ ان کے سینوں میں سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہونے لگتی ہے.ان میں سے کوئی معنے لے لئے جائیںخواہ یہ معنے لے لئے جائیںکہ ضَبْحٌ گھوڑے کی ایک تیز دوڑ کا نام ہے تب بھی.اگر یہ معنے لئے جائیںکہ اس میں گھوڑوں کی اس حالت کا ذکر ہے جبکہ وہ لمبا کود کود کر پائوںمارتے ہیںتب بھی.اور اگر یہ معنے لئے جائیںکہ اس میں گھوڑوں کی اس دوڑ کا ذکر ہے جس میںان کے سینہ میں سے ایک
Page 122
خاص قسم کی آواز پید اہونے لگتی ہے تب بھی.ان تینوں صورتوں میں یہ امر ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایسے گھوڑوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جوش و خروش سے اور انتہا ئی رغبت اور شوق سے دوڑتے ہیں.یہ سیدھی بات ہے کہ گھوڑا خود نہیں دوڑتا بلکہ دوڑانے والا اسے دوڑاتا ہے اس لئے گو یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے مگر اس سے مراد وہ سوار ہیں جو گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے ہیںیا گھوڑوں کو اس طرح دوڑاتے ہیںکہ ان کے سینوں میں سے آوازنکلنی شروع ہو جاتی ہے وہ ذرا بھی پروا نہیں کرتے کہ ان کا گھوڑا زندہ رہتا ہے یا مرتا ہے یا اس قدر ان میں جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو کُداتے جاتے ہیں.تفسیر.سورۃ عادیات میں غزوات اسلامیہ کے متعلق پیشگوئی مجھے اس سورۃ کے متعلق یہ خاص طور پر خوشی ہے کہ خود صحابہؓ نے اس کے ایسے معنے کئے ہیںجن سے یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی کی حامل قرار پاتی ہے.بہت کم آیات ایسی ہیں جن کے معنے کرتے ہوئے گذشتہ مفسرین نے ان کو کسی پیش گوئی کا حامل قراردیا ہو.میں سمجھتا ہوںکہ ایسی آیات کی تعداد پانچ سات سے زیادہ نہیں ہو گی.با لعموم پرانے مفسر ین کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو یا قیامت پر چسپاں کر دیتے ہیںیا بعض گذشتہ واقعات کی طرف ان کو منسوب کر دیتے ہیں.لیکن اس آیت کے متعلق گوحضرت علیؓاور بعض دوسرے صحابہؓ کا یہ بھی قول ہے کہ اس میں حج کا ذکر ہے لیکن حضرت عبد اللہ بن عباسؓبڑے اصرار کے ساتھ اس امر پر قائم تھے کہ اس سورۃ میں غزوات اسلامیہ کا ذکر ہے اور ان حملوں کی خبر دی گئی ہے جو مسلمانوں نے کفار پر کرنے تھے(فتح البیان سورۃ العادیات زیر آیت وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا).یہاں آکر ریور نڈویری کا ہمارے ساتھ متفق ہو جانا اور کہنا کہ یہ سورۃ مکی ہے کوئی معمولی بات نہیں.غالباً ان کا ذہن حج کی طرف ہی چلا گیا ہے ورنہ اگر انہیںپتہ ہوتا کہ مکہ میں گھڑ چڑھے سواروں کا ذکر غزوات اسلامیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک زمانہ میں مسلمانوںکو کفار سے لڑائیاں کرنی پڑیں گی تو وہ کبھی اس سورۃ کو مکی قرار نہ دیتے.بہرحال گھوڑے کا کودنا مالک کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے.پس گو یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے مگر دراصل وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا میں سواروں کے جوش کا اظہار ہے.ضَبْحًا خواہ تیز دوڑ کا نام ہو، خواہ دوڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہو، خواہ ٹانگیں اٹھا اٹھا کر دوڑنا یا کداتے چلے جانا مراد ہو بہرحال گھوڑا خود نہیں دوڑتا بلکہ اسے سوار دوڑاتا ہے.پس یہ تینوں حالتیں سوار کے قلب کی کیفیت کے متعلق ہیں اور مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا اس قدر جوش ہوگا کہ وہ بے تحاشا اپنے گھوڑوں کو ایڑیاں مار مار کر دوڑاتے ہوئے دشمن کے ملک کی
Page 123
طرف جائیں گے اور اس امر کی ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کے گھوڑے مرتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں.اگر ضَبْحٌ کے معنے خاص قسم کی تیز چال کے کئے جائیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ سوار آہستہ چلنا برداشت نہیں کرسکیں گے اور اگر اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتے چلے جائیں گے تب بھی اس کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ منزل مقصود سے پیچھے رہنا برداشت نہیں کرسکیں گے.غرض تینوں صورتوں میں اس کا ایک ہی مفہوم ہوگا کہ سوار منزل مقصود کی طرف اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا چلا جائے گا مگر اس لئے نہیں کہ وہاں اس کی محبوبہ بیٹھی ہے جس کی ملاقات کے لئے وہ بے تاب ہورہاہے.اس لئے بھی نہیں کہ وہاں کسی نے بڑے بڑے اچھے کھانے تیار کئے ہوئے ہیں اور اسے ان کھانوں میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے.اس لئے بھی نہیں کہ وہاں اس کا مال و متاع پڑا ہوا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کوئی چور اسے اٹھا کر نہ لے جائے.اس لئے بھی نہیں کہ وہاں اس کے دوست احباب موجود ہیں اور وہ ان سے ملنے کے لئے مسافت کو جلد طے کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ اس جگہ جارہا ہے جہاں دشمن اس کی جان لینے کا منتظر بیٹھا ہے اور اس لئے جارہا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کردوں.گویا ڈر اور خوف کی بجائے اس کے دل میں خوشی اور امنگ ہوگی اور وہ انتہائی مسرت اور شادمانی کے جذبات کے ساتھ میدان قتال کی طرف بڑھتا چلا جائے گا.وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا میں مسلمانوں کی قلبی کیفیات کا ذکر پس وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا میں گو ذکر گھوڑوں کا ہے مگر حقیقتاً اس میں ان مسلمانوں کی قلبی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے جو ان پر سوار ہوں گے.وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا کے متعلق صحابہ کے اقوال اس آیت کے معنوں کے متعلق بھی مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں.عبداللہ (بن مسعودؓ) کہتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہیں.حضرت علیؓ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہیں.لیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں.چنانچہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے دنوں میں خانۂ کعبہ کے پاس حطیم میں بیٹھا ہوا عبادت کررہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے آپ سے ایک آیت کا مطلب دریافت کرناہے.میں نے کہا پوچھو.کہنے لگا وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا کے کیا معنے ہیں؟ میں نے کہا ا س سے گھوڑے مراد ہیں.اس نے جاکر حضرت علیؓ سے اس کا ذکر کردیا یا کسی اور طرح حضرت علیؓ کو یہ بات پہنچ گئی جس پر آپ نے فرمایا یوم بدر میں تو ہمارے پاس گھوڑے نہ تھے.گھوڑے تو پہلی دفعہ ایک سریہ میں گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تھا(فتح البیان سورۃ العادیات زیر آیت وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا).ابن جریر حضرت ابن عباسؓ کی ایک دوسری روایت میں اس واقعہ کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ میں
Page 124
ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا.فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا کے متعلق سوال کیاکہ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا گھوڑے سوار جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دھاوا کرنے کے بعد واپس رات کو آتے ہیں توکھانا پکانے کے لئے آگ جلاتے ہیں.اس نے جاکر حضرت علیؓ سے کہا انہوں نے کہا کیا کسی اور سے بھی پوچھا ہے؟ اس نے کہا ہاں عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا ہے.انہوں نے کہا جائو اور ان کو بلالائو.جب میں گیا تو حضرت علیؓ نے خفا ہوکر کہا کیا تو اس امر کا فتویٰ دیتا ہے جس کا تجھے علم نہیں.پہلا غزوہ اسلام میں بدر تھا اور اس میں صرف دو گھوڑے ہمارے ساتھ تھے.ایک گھوڑا زبیرؓ کا تھا اور ایک مقدادؓ کا.پھر کہا الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا سے مراد حاجی ہیں جو عرفہ سے مزدلفہ کی طرف اور پھرمزدلفہ سے منیٰ کی طرف آتے ہیں (عرفہ سے مزدلفہ تیزی سے آتے ہیں) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر اپنے قول سے رجوع کرلیا (طبری زیر سورۃ العادیات).مگر باوجود اس کے کہ ابن جریر نے یہ روایت لکھی ہے.ابن جریر بھی کہتے ہیں کہ اس کے معنے گھوڑوں کے سوا اور کچھ نہیں بنتے.اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے سب شاگرد انہی معنوں کے قائل ہیں اور دوسرے علماء بھی یہی معنے مراد لیتے ہیں.چنانچہ مجاہد، عکرمہ، عطاء، قتادہ اور ضحاک سب کا یہی قول ہے اور ابن عباسؓ اور عطاء سے یہ مروی ہے کہ گھوڑے اور کتے کے سوا کوئی ضَبْحٌ نہیں کرتا.(طبری زیر سورۃ العادیات) حل لغات میں بھی بتایا جاچکا ہے کہ ضَبْحٌ اس آواز کو کہتے ہیں جو تیز دوڑتے وقت گھوڑوں کے سینوں سے پیدا ہوتی ہے.پس باوجود اس روایت کے جس میں یہ ذکر کیاگیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنے قول سے رجوع کرلیا ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عبداللہ بن عباسؓ کا آخر تک یہی مذہب رہا.اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کے سب شاگرد انہی معنوں پر کیوں عمر بھر زور دیتے رہتے.پس لغت کی شہادت اور ائمہ ادب کے اصرار کے بعد ہم مجبور ہیں کہ وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا سے گھوڑے ہی مراد لیں.گو استعارۃً اس سے اونٹ بھی مراد لئے جا سکتے ہیںاور یہ جو کہا گیا ہے کہ اس آیت کوغزوات اسلامیہ پر اس لئے چسپاں نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ بدر میں مسلمانوںکے پاس گھوڑے نہیں تھے میرے نزدیک درست نہیںبے شک بدر کی جنگ میں صحابہؓ کے پاس زیادہ گھوڑے نہیںتھے مگر بعد کی جنگوں میں وہ کثرت کے ساتھ گھوڑے رکھنے لگ گئے تھے.بدر کی جنگ پر اس آیت کو چسپاں کرتے ہوئے ہم عَادِیَات سے استعارۃً اونٹ مراد لے لیں گے جس طرح وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا کے اصل معنے دوڑنے والے گھوڑوں کے ہیںلیکن ہم نے اس کے معنے سواروں کے کئے ہیںکیونکہ گھوڑا خود نہیں دوڑتا بلکہ سوار اسے دوڑاتا ہے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیںکہ گو وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا سے گھوڑے مراد ہیں مگر بدر میں اس سے استعارۃً اونٹ مراد تھے کیونکہ عربی زبان میں یہ عام طریق ہے کہ بعض دفعہ ایک بڑی چیز کا ذکر
Page 125
کر دیا جاتا ہے اور چھوٹی چیز کا ذکر اس میں خود بخود شامل سمجھا جاتا ہے.مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو عورتیں اس میںطبعی طور پر شامل سمجھی جاتی ہیں.اسی طرح اغارت میں چونکہ گھوڑے زیادہ کام آیا کرتے ہیںاس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا اونٹوں کا نام نہیں لیا مگر اونٹ جب جنگی کاموں میں استعمال ہوںاستعارۃً اس میں خود بخود آجاتے ہیں.پس اگر جنگ بدر پر ان آیات کو چسپاںکرتے ہوئے عادیات سے اونٹ مراد لے لئے جائیںتو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ بعد میں جوں جوں دن گذرتے گئے صحابہ میں گھوڑوں کا استعمال بڑھتا چلا گیا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوڑے استعمال کرنے لگے یہاں تک کہ حدیثوں سے دس کے قریب گھوڑے اور گدھے ثابت ہیں (البدایۃ والنـھایۃ ذکر افراسہ و مراکیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ) جو مختلف وقتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے استعمال کئے.بہر حا ل اکثر صحابہ کی یہ رائے ہے کہ اس سورۃ میں ان غزوات کی خبر دی گئی ہے جو مسلمانوں کو کفار سے پیش آئے چنانچہ ایک حدیث بھی معین صورت میں اس کی تائید میں آتی ہے.ایک صحابی یہ بیان کرتے ہیں وَالْعٰدِيٰتِ کی سورۃکا شان نزول یہ تھا کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کنانہ کی طرف ایک سریہ بھجوایا جس کے سردار المنذر بن عمر و الانصاری تھے(یہ لشکر گھوڑوں پر سوار تھا جیسا کہ حضرت علیؓ کی اوپر بیان کردہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے اس قول کی خبر پہنچی کہ عَادِیَاتِ ضَبْحًا سے گھوڑے مراد ہیںتو آپ نے فرما یا کہ گھوڑے تو ایک سریہ میں گئے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوائے تھے) المنذر ان بارہ نقباء میں سے ایک تھے جنہوں نے مکہ میںرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے اپنے قبیلہ کا سردار اور افسر مقرر فرمایا تھا.ایک ماہ تک اس سریہ کے بارہ میں کوئی خبر نہ آئی جس پر منافقوں نے شور مچادیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ سب کے سب مارے گئے ہیں.ان کا مقصد ان افواہوں سے یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیںاور آئندہ وہ کسی قسم کی قربانی کے لئے باہر نہ نکلیںجب انہوں نے اس رنگ میں جھوٹا پرا پیگنڈہ شروع کر دیا تویہ سورۃ نازل ہوئی جس میں اس سریہ کا نقشہ کھینچا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ سلامت ہیں انہوں نے دشمن پر حملہ کیا ہے اور وہ اپنے حملہ میں کامیاب رہے ہیںچنانچہ چند دنوں کے بعد سریہ واپس آگیا اور اس نے بتایا کہ جس طرح پیش گوئی کی گئی تھی ویسے ہی واقعات اس کے ساتھ پیش آئے ہیں.(فتح البیان سورۃ العادیات زیر آیت وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا) یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ تو مکی ہے لیکن اگر اس روایت کو درست تسلیم کیا جائے تو اس کے معنے یہ بنتے
Page 126
ہیںکہ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی تھی مکہ میں نہیں.ایک طرف اسے مکی قرار دینا اور دوسری طرف اس آیت کا شانِ نزول ایسا بتانا جس سے یہ مدنی ثابت ہو عجیب بات ہے.اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسا میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوںیہ امر کثرت سے ثابت ہے کہ ایک ایک آیت کے کئی کئی شان نزول بتائے گئے ہیںاور محققین کا قول ہے کہ در حقیقت شان نزول کے معنے صرف اتنے ہوتے ہیںکہ فلاں آیت فلاں واقعہ پر بھی چسپاںہوتی ہے یہ معنے نہیں ہوتے کہ وہی واقعہ اس آیت کا شان نزول تھا اس جگہ بھی یہی مراد ہے یعنی چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں سب یا بکثرت گھوڑے استعمال کئے گئے تھے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلٖ وسلم نے اس پہلے سے نازل شدہ سورۃ کو ان لوگوں پر جو ایسی خبریں مشہور کرتے تھے چسپاں کیا اور یہ استدلال فرمایا کہ جس سورۃ میں گھڑ سواروں کی خبر ہے وہ ضرور پہلی گھڑ سواروںکی فوج پر تو پوری ہو گی اور چونکہ اس سورۃ میںاسلامی گھڑسواروں کے جیتنے کی خبر ہے اس لئے ضرور یہ لشکر جیت کر آئے گا.پس آپ نے اس سورۃ سے استنباط کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ سوار جنہیںمیں نے بھجوایا ہے اس پیش گوئی کے ماتحت جیت کر آئیں گے اور تمہاری مایوسانہ طبیعت کا پول کھل جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب منافقین نے یہ افواہیں مشہور کی ہوںتو اللہ تعالیٰ نے اسی پرانے کلام کو دوبارہ نازل کرکے مسلمانوں کو تسلی دی ہو کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیںسریہ واپس آئے گا اور کامیاب وکامران واپس آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بارہ میں پہلے سے پیش گوئی کر چکا ہے اور تم سمجھ سکتے ہو کہ بہر حال اللہ تعالیٰ کی ہی پیش گوئی پوری ہو گی منافقین کی بات سچی نہیں ہو سکتی.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃوالسلام نے تحریر فرمایا ہے کہ:.’’ایک مقدمہ میںکہ اس عاجز کے والد مرحوم کی طرف سے اپنے زمینداری حقوق کے متعلق کسی رعیت پر دائر تھا.اس خاکسار پر خواب میں یہ ظاہر کیا گیا کہ اس مقدمہ میں ڈگری ہو جائے گی چنانچہ اس عاجز نے وہ خواب ایک آریہ کو کہ جو قادیان میں موجود ہے بتلادی.پھر بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ اخیر تاریخ پر صرف مدعا علیہ مع اپنے چند گواہوں کے عدالت میں حاضر ہوا اور اس طرف سے کوئی مختار وغیرہ حاضر نہ ہوا.شام کو مدعا علیہ اور سب گواہوں نے واپس آکر بیان کیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا.اس خبر کو سنتے ہی وہ آریہ تکذیب اور استہزاء سے پیش آیا.اس وقت جس قدر قلق اور کر ب گذرا بیان میں نہیں آسکتا.کیونکہ قریب قیاس معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک گروہ کثیر کا بیان جن میںبے تعلق آدمی بھی تھے خلاف واقعہ ہو.اس سخت حزن و غم کی حالت میںنہایت شدت سے الہام ہواکہ جو آہنی میخ کی طرح دل کے اندر داخل ہو گیا.اور وہ یہ تھا.ڈگری ہو گئی ہے مسلمان ہے.
Page 127
یعنی کیا تو باور نہیں کرتا اور باوجود مسلمان ہونے کے شک کو دخل دیتا ہے.آخر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ فی الحقیقت ڈگری ہی ہوئی تھی اور فریق ثانی نے حکم کے سننے میں دھوکا کھایا تھا‘‘ (براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد ۱ صفحہ ۶۵۸،۶۵۹) اب دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃوالسلام اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ایک خبر دیتے ہیںاور واقعہ اس کے مطابق ہو تا ہے مگر جب آریہ جھوٹی افواہ مشہور کر دیتا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے اور دوبارہ بتاتا ہے کہ’’ڈگری ہو گئی ہے مسلمان ہے‘‘ یعنی تم مسلمان ہو تمہیں خدا تعالیٰ کے کلا م پر یقین رکھنا چاہیے واقعہ یہی ہے کہ ڈگری ہو گئی ہے.اسی طرح جب منافقین نے جھوٹی افواہیں پھیلانی شروع کر دیںتو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا والی آیات دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی ہوں یہ بتانے کے لئے کہ تم نے ہی جیتنا ہے اور اس بارہ میںہم پہلے سے پیش گوئی کر چکے ہیںمنافقوں کا کیا ہے وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں.غرض میرے نزدیک یہ دونوں صورتیں ممکن ہیںیہ بھی کہ جب یہ پہلا سریہ گیا اور منافقوں نے مشہور کر نا شروع کر دیا کہ مسلمان سب مارے گئے ہیںتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فر مایا ہو کہ وہ کس طرح مارے جا سکتے ہیں.یہ پہلا سریہ ہے جو گھوڑوں پر گیا ہے اور اس لحاظ سے اس پیش گوئی کا پہلا مصداق ہے جو خدا تعالیٰ نے وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا میں کی ہوئی ہے اس لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مارے جائیں اور سننے والے نے سمجھا ہوکہ اسی واقعہ پر یہ سورۃ نازل ہوئی ہے.حا لانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ ہمیں فتح ہو گی تو منافقوں کی یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے کہ مسلمان مارے گئے ہیں.اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مکی آیات دوبارہ مسلمانوں کی تسلی کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر نازل کر دی گئی ہوں.بہر حال کوئی صورت ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پیشگوئی قرار دیا ہے جو ثبوت ہے اس بات کا کہ غزوات اسلامیہ پر ان آیات کو چسپاں کرنا بالکل درست ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ان معنوں کو حاصل ہے.یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لغت میںبعض دوسرے جانور وں کی آواز کو بھی ضَبْحٌ کہا جاتا ہے.مثلاً اُلو کی آواز کو بھی ضَبْحٌ کہتے ہیں.لومڑ کی آواز کو بھی ضَبْحٌ کہتے ہیں.کالے سانپ کی آواز کو بھی ضَبْحٌ کہتے ہیں.خر گوش کی آواز کو بھی ضَبْحٌ کہتے ہیں.ان جانوروںکی آواز کے علاوہ کمان سے جو آواز نکلتی ہے اسے بھی ضَبْحٌ کہتے ہیںاور اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنی چیزوں کے لئے ضَبْحٌ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا کو
Page 128
گھوڑوںپر مخصوص طور پر کس طرح چسپاں کیا جا سکتا ہے کیوں نہ یہ سمجھ لیا جائے کہ وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا والی آیت اونٹوںپر بھی چسپاں ہو سکتی ہے اور حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بیان کردہ معنے با لکل درست ہیں.اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک استعارہ اور مجاز کا سوال ہے ہم خود تسلیم کرتے ہیںکہ عٰدِیٰتِ ضَبْحًا میں اونٹ بھی شامل ہیں.کیونکہ جب اس چیز کا ذکر کر دیا گیا ہے جو اغارت میں زیادہ کام آتی ہے یعنی گھوڑے.تو اونٹوں کا ذکر مجازی طور پر اس میں خود بخود شامل سمجھا جائے گا کیونکہ اونٹ بھی اغارت میں کام آتے ہیںگو گھوڑوں کی نسبت کم.لیکن اگر صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اُلو یا بعض دوسرے جانوروں کی آواز کے لئے بھی ضَبْحٌ کا لفظ بول لیتے ہیں یہ کہا جائے کہ چونکہ اُلو یا فلاں جانور کی آواز کو بھی ضَبْحٌ کہا جاتا ہے اس لئے ہم اس جگہ وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا سے اونٹ مراد لیں گے تو یہ قیاس مع الفارق ہو گا کیونکہ اونٹ اور اُلو میں تو کوئی جوڑ ہی نہیںسوائے اس کے کہ کوئی مزاحیہ رنگ میں کہہ دے کہ اونٹ اور اُلو میںکیوں جوڑ نہیں.اُلو میں بھی الف وائو آتا ہے اور اونٹ میں بھی الف وائو آتا ہے.اس میں کوئی شبہ نہیںکہ ضَبْحٌ کا لفظ بعض دوسرے جانوروںکی آواز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مگر عَادِیَات کے ساتھ مل کر ضَبْحًا کے جو معنے بنتے ہیںوہ سوائے گھوڑوں کے اور کسی چیز پر چسپاں نہیں ہو سکتے.یوں خالی ضَبْحٌ کا لفظ بے شک خرگوش یا اُلو یا لومڑ کی آواز کے لئے استعمال کر لیاجاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہاںخالی ضَبْحٌ کا لفظ نہیں بلکہ وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا کے الفاظ ہیںاس لئے اس آیت کے معنے کرتے ہوئے وَ الْعٰدِيٰتِ سے ایسے دوڑنے والے ہی مراد لئے جائیں گے جن کے سینہ سے تیز دوڑتے ہوئے آواز نکلتی ہو اور اس آواز کو ضَبْحٌ کہا جاتا ہو.اور میں بتا چکا ہوںکہ لغت میں صاف طور پر لکھا ہے کہ ضَبْحٌ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو تیز دوڑتے وقت گھوڑوں کے سینوں میں سے نکلتی ہے پس وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا سے گھوڑے ہی مراد ہوں گے نہ کہ کوئی اور چیز.اور اِبِل کا ذکر بھی استعارۃً سمجھا جائے گا نہ کہ حقیقی معنوں میں.اس آیت کا یہ بھی ایک لطیف پہلو ہے کہ مکہ میں گھوڑے بہت کم ہوتے ہیںوہاں زیادہ تر اونٹوں کا رواج ہے.جب میں حج کے لئے گیا تو سواری کے لئے گدھا تو مل جاتا تھا مگر گھوڑا نہیں ملتا تھا.ہمارے ملک میںچونکہ گدھے پر سوار ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ گھوڑا تلاش کرو بڑی تلاش کے بعد گھوڑا تو نہ ملا ایک خچر مل گئی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ یہ تین ہزار روپیہ کی ہے میں اس پر سوار ہو گیا.ہم اس وقت غار ثور کی طرف جارہے تھے ا ور میرے باقی ساتھی گدھوں پر سوار تھے.میرے ساتھی تو آدھ میل آگے نکل گئے مگر میں پیچھے رہ گیا
Page 129
آخر میں نے بھی خچر چھوڑی اور گدھے پر سوار ہو کر وہاںپہنچا.پس مکہ میں گھوڑے بہت کم ہوتے ہیںاور اس زمانہ میںتو اور بھی کم تھے.جب یہ سورۃ نازل ہوئی زیادہ تر اونٹوں کا رواج تھا مگر اللہ تعالیٰ نے وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا کی آیت نازل فرما کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ یہ مکہ کے اونٹ سوار ایک دن گھوڑے سوار بننے والے ہیں.چنانچہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوںبعد میں مسلمانوں کے پاس گھوڑے بڑھتے چلے گئے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی کیونکہ جنگ میں جتنا کام گھوڑا دے سکتا ہے اتنا کام اونٹ نہیں دے سکتا.اس کے علاوہ مسلمانوں میں گھوڑوں کا رواج اس وجہ سے بھی ترقی پا گیا کہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے گھوڑے رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کا ایک ذریعہ قرار دے دیا تھا.مثلاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر یہ حکم دے دیا تھا کہ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ (الانفال:۶۱) تم اپنے دشمنوں کے مقابلہ میںجو کچھ بھی تیاری کر سکتے ہو کرو اپنی قوت کو بڑھا کر اور اپنے گھوڑوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے تاکہ اس ذریعہ سے دشمن پر تمہارا رعب قائم ہو جائے اور وہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز آجائے.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ جہاد کے لئے گھوڑے رکھیں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے گا.مثلاً آپ نے فرمایا اَلْـخَیْل مَعْقُوْدٌ فِیْ نَوَاصِیْـہَا الْـخَیْـرُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَۃِ(بخاری کتاب الـجھاد والسیر باب الخیل معقود فی نواصیھا الـخیر الی یوم القیامۃ) کہ گھوڑوں کی پیشانی میںقیامت تک خیر بندھی ہوئی ہے اسی طرح آپؐنے فرمایا مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِیْ سَبِیْلِ اللہِ اِیْـمَانًا بِاللہِ وَتَصْدِیْقًا بِوَعْدِہٖ فَاِنَّ شَبْعَہٗ وَ رَیَّہٗ وَرَوْثَہٗ وَبَوْلَہٗ فِیْ مِیْـزَانِہٖ یَوْمِ الْقِیَامَۃِ (بخاری کتاب الجھاد والسیر باب من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ) کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنا گھوڑا وقف کر دیتا ہے اس گھوڑے کا کھانا، اس کا پینا، اس کی لید اور اس کا پیشاب سب قیامت کے دن انسان کی میزان میں بطور اعمال نیک کے تولے جائیں گے.گھوڑوں کے متعلق تو اس قسم کی متعدد احا دیث آتی ہیںمگر اونٹ کے متعلق کسی حدیث میں نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے اس کا رکھنا بھی اسی طرح موجب حسنات قرار دیا ہو.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منشاء الٰہی یہی تھا کہ مسلمان گھوڑے زیادہ رکھیںاور اغراض جہاد کے لئے اونٹوں کی طرف کم توجہ کریں.یہ ساری باتیں بتاتی ہیںکہ اس جگہ عَادِیَات سے گھوڑے ہی مراد ہیں چنانچہ قرآن کریم سے بھی اس کی
Page 130
تصدیق ہو گئی حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی اور لغت کی تائید بھی ان معنوں کو حاصل ہو گئی.کیونکہ لغت بتاتی ہے کہ ضَبْحٌ گھوڑے کی ایک دوڑ کا بھی نام ہے اور ضَبْحٌ اس خاص قسم کی آواز کو بھی کہا جاتا ہے جو دوڑتے وقت اس کے سینہ میں سے نکلتی ہے اور وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا کے معنے یہ ہیںکہ اےـ مسلمانو! آئندہ زمانہ میں تمہیں جنگیں پیش آنے والی ہیںتمہاری ملکی چیز اونٹ ہے مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ تمہیں اپنے پاس زیادہ سے زیادہ گھوڑے رکھنے چاہئیں کیونکہ وہ جنگ میں اونٹوںسے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں.اگر تم گھوڑوں سے کام لو گے تو وہ تمہاری فتح کا موجب ہو جائیں گے.چنانچہ صحابہ ؓ نے ایسا ہی کیا اور روز بروز ان کے گھوڑے بڑھتے چلے گئے.فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًاۙ۰۰۳ پھر (مجھے قسم ہے) چوٹ مار کر چنگاری نکالنے والوں کی حلّ لُغات.مُوْرِیَاتِ مُوْرِیَاتِ: اَوْرٰی سے اسم فاعل کا جمع مونث کا صیغہ ہے اور اَوْرَی الزَّنْدَ کے معنے ہوتے ہیںاَخْرَجَ نَارَہٗ (اقرب).اس نے چقماق میں سے آگ نکالی یعنی چقماق کو ٹکرایا جس کے نتیجہ میں آگ پیدا ہوئی اور قَدَحَ بِالزَّنْدِ کے معنے ہیں رَامَ الْاِیْرَاءَ بِہٖ اس نے چقماق میں سے آگ نکالنے کا ارادہ کیا (اقرب) قَدْحًا پس فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا کے معنے یہ ہوئے کہ وہ قَدْح کر کے یعنی ارادہ کے ساتھ آگ نکالتے ہیں یا قَدْح کے معنے چونکہ بعض لوگ ٹکرانے کے لیتے ہیںاس لحاظ سے معنے یہ ہوں گے کہ وہ ٹکرا کر آگ نکالتے ہیں.تفسیر.آگ جلانے سے بعض نے گھوڑوں کے سموں سے پیدا ہو نے والیآگ مراد لی ہے (ابن جریر) اور بعض نے جنگ سے واپسی پر کھانا پکانے کی آگ یا مزدلفہ میںآگ جلانا مراد لیا ہے.حضرت ابن عباسؓنے جنگ سے واپسی پر کھانا پکانے کے لئے آگ جلانا ہی اس کے معنے کئے ہیں(طبری سورۃ العادیات زیر آیت فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ).پرانے زمانے میں چونکہ دیا سلائیاں نہیں ہوتی تھیں اس لئے گھروں میںعام طور یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ رات کو کھانا پکانے کے بعد کسی قدر آگ راکھ میں دفن کر دی جاتی تھی بلکہ آج کل بھی دیہات میں یہی طریق رائج ہے جب شام کا کھاناتیار ہو جاتاہے تو کوئی انگارہ یا سلگتی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا راکھ کے نیچے دفن کر دیتے ہیںصبح کے وقت انگارہ نکال کر تھوڑی سی مونج کی رسی اس پر رکھ دیتے ہیںیا لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اکٹھے کر کے اس کے ارد گرد رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مونج یا لکڑی کے ٹکڑے جل اٹھتے ہیں اور آگ روشن ہو جاتی ہے وہ لوگ جن کی آگ بجھ
Page 131
جاتی ہے اپنے ہمسایہ سے آگ لے لیتے ہیںمگر جنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا اس موقعہ پر پرانے زمانہ میں آگ روشن کرنے کے لئے چقماق سے کام لیا جاتا.چقماق کو جب لوہے سے زور سے ٹکرائیںتو اس میں سے آگ نکلتی ہے اس وقت ذرا سا کپڑایا سوکھا ہو ا پتّہ یا مونج کا کوئی ٹکڑا ساتھ رکھ دیا جائے تو وہ فوراً جل اٹھتا ہے.آج کل بھی یورپین قوموں میںچقماق کا رواج پایا جاتا ہے مگر ہمارے ملک میں اس کا رواج مٹ گیا ہے.جب ہم چھوٹے تھے تو چقماق سے تماشہ کے طور پر آگ نکالا کرتے تھے اور گنوار لوگ جن کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ بڑا معجزہ ہو گیا ہے مگر اب ہندوستا ن میں چقماق کا رواج نہیں رہا.جرمن قوم میں اس کا زیادہ رو ا ج ہے کسی قدر انگریزوں میں بھی اس کا رواج پایا جاتا ہے چنانچہ جنگ کے دنوں میںسگرٹ اور سگار جلانے کے لئے فوجیوں میں چقماق بھی دیئے جاتے تھے.چقماق کو ایک گھومنے والے لوہے کے چکر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور ساتھ ایک سپرنگ لگا ہوا ہوتا ہے جب اس سپرنگ کو دبایا جائے تو لوہے کا چکر تیزی کے ساتھ گھومنے لگتا ہے اور ساتھ کے چقماق کے ساتھ ٹکراتا ہے جس سے شعلہ پیدا ہوتا ہے پاس ہی بتی ہوتی ہے جس کے نیچے کچھ تیل ہوتا ہے وہ فوراً اس شعلہ سے جل اٹھتی ہے اور سگرٹ یا سگار جلا لیا جاتا ہے اور پھر فوراً بتی کو بجھا دیا جاتا ہے.جرمنوں میں اس کا رواج بہت زیادہ تھا مگر جرمن تجارت کا یہ آلہ ایک جزو تھا.تھوڑے دن ہوئے یہاں کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ فوجیوںکے لئے سگار لائٹر تیار کئے گئے ہیں یہ سگار لائٹر زیادہ تر برما میں کام کرنے والے فوجیوں کے لئے تیار کئے گئے تھے کیونکہ وہاں آگ آسانی سے نہیں جل سکتی.فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا کے معنے ابن عباسؓکے نزدیک پرانے زمانہ میں بوجہ دیا سلائی نہ ہونے کے فوجوں میں چقماق سے ہی زیادہ تر کام لیا جاتا تھا اس لئے حضرت ابن عباس ؓکی یہ رائے ہے کہ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا کے معنے یہ ہیںکہ جب وہ سوار جنگوں سے واپس آتے ہیںتو بیٹھ کر آگ جلاتے اور اپنے لئے کھانا تیار کرتے ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا کے فقرہ کے معنے حضرت ابن عباس ؓ کے قول کے مطابق کھانا پکانے کے لئے آگ جلانے کے بھی ہوسکتے ہیں مگر یہاںوہ بات مراد نہیں جو انہوں نے سمجھی ہے یعنی وہ حملہ سے لوٹ کر ایسا کرتے ہیں کیونکہ اس کی تردید اگلی آیت سے ہی ہو جاتی ہے.اگلی آیت میں حملہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے پہلے فاء ہے جو اکثر وبیشتر ترتیب کے لئے آتی ہے.یہ ترتیب خود بتا رہی ہے کہ حملہ بعد میں ہے نہ کہ پہلے.یعنی پہلے فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ہے اور پھر فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا.پس اگلی آیت میںمذکور بات اس آیت میں بتائی ہوئی بات کے بعد ہونی چاہیے.میرے نزدیک فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا کے معنے اگر کھانا پکانے کے لئے آگ جلانے کے ہی کرنے ہوںتو چونکہ
Page 132
اس کے بعد حملہ کرنے کا ذکر ہے اس کے یہ معنے کرنے زیادہ درست ہوں گے کہ صحابہؓ حسب سنت نبویؐ جب حملہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو فوراً حملہ نہیں کر دیتے بلکہ قریب جا کر سواریوں سے اترجاتے ہیںاور کھانا وغیرہ پکاتے اور رات گذارتے ہیںپھر صبح کو حملہ کرتے ہیں.تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں یہ بات داخل تھی کہ آپ کبھی سیدھا حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ جہاں حملہ کرنا ہوتا اس مقام سے ایک دو میل دور اپنے ڈیرے لگا دیتے اور جب صبح ہوتی تب حملہ کرتے.(صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث کعب بن مالک) پس اگر اس آیت سے کھانا پکانے کے لئے آگ جلانا ہی مراد ہو تو بھی جنگ سے واپسی پر کھا نا پکانا مراد نہیں بلکہ حملہ سے پہلے کھانا پکا نا مراد ہے.اگر فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا میں حملہ کے بعد آگ روشن کرنے اور کھانا پکانے کا ذکر ہوتا تو اس کے بعد فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا نہ آتا اللہ تعالیٰ کا پہلے فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا رکھنا اور پھر فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا کہنا صاف بتا رہا ہے کہ اس آیت میں حملہ سے واپسی کا ذکر نہیں بلکہ ذکر یہ ہے کہ جب وہ حملہ کرنے جاتے ہیںتو فوراًحملہ نہیںکردیتے بلکہ رات کو ٹھہرتے آگ جلاتے اور کھانا وغیرہ پکاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تب حملہ کرتے ہیں.فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا میں مسلمانوں کے ایک خُلق کی طرف اشارہ ان آیات میں ایک طرف تو یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنی جان دینے کا اس قدر جوش پایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے زبر دست اور کثیر التعداد دشمنوں کے مقابل پر جاتے ہیںتو وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑیاں مارتے اور ان کو دوڑاتے اور کداتے چلے جاتے ہیںاور اس امر کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے کہ ان کے گھوڑے زندہ رہتے ہیں یا مر تے ہیں.مگر دوسری طرف ان میں ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اسلامی پائے جاتے ہیںکہ جب وہ عین دشمن کے سر پر پہنچ جاتے ہیںاس وقت یک دم حملہ نہیں کرتے بلکہ منزل کرتے ہیںاور کھانا پکاتے ہیںاور رات بسر کرتے ہیںپھر جب صبح ہوتی ہے تب حملہ کرتے ہیں.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عمر یہ معمول رہا کہ آپ کبھی رات کو حملہ نہیں کرتے تھے اور نہ صحابہ ؓ کو شب خون مارنے کی اجازت دیتے تھے.دراصل عرب میں الگ الگ قبائل ہوا کرتے تھے اور وہ خانہ بدوش ہونے کی وجہ سے اپنی جگہیں ہمیشہ تبدیل کرتے رہتے تھے اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ میں بہت محتاط پہلو اختیار فرماتے تھے.آپ فرماتے کہ کبھی رات کو حملہ نہ کرو ممکن ہے ایک قبیلہ اٹھ جائے اور دوسرا قبیلہ اس کی جگہ آبیٹھے اور تم غلطی سے دشمن کی بجائے کسی اور پر حملہ کر دو.اس لئے صبح تک انتظار کرو اگر صبح کو ان کی اذان کی آواز تمہارے کان میں
Page 133
آجائے تو تم حملہ نہ کرو اور اگر تم نے حملہ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ تمہاری اذان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمان حملہ کرنے کے لئے آگئے ہیںسوتے دشمن پر حملہ نہیں کرنا.پس فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا میں صحابہؓ کے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آج مکہ میںمسلمان مغلوب ہیںوہ قریش کے بڑے بڑے رئووسا کی نگاہ میں مقہور اور ذلیل ہیں.دشمن اٹھتا ہے اور انہیں بے دریغ تکالیف دینا شروع کر دیتا ہے اسے کسی خُلق کی پروا نہیںوہ اپنا واحد مقصد یہ سمجھتا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو دکھ دے خواہ اخلاق میں سے کوئی ایک خُلق بھی اس کے پاس نہ رہے.مگر یاد رکھو ایک دن یہ بےکس اور کمزور نظر آنے والے لوگ بھی ترقی کرجائیں گے اور اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی جانیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے آئیں گے.عربوں کے لئے گھوڑا عجیب چیز تھی صرف نجدیوں کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے اور نجدیوں سے مکہ والے بڑے گھبراتے تھے مگر اللہ تعالیٰ پیشگوئی کرتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے اور اپنے پاس کثرت سے گھوڑے رکھنے لگیں گے تم سمجھتے ہو کہ چونکہ مسلمان کمزور ہیں اس لئے جانیں دے رہے ہیں مگر یہ با لکل غلط ہے.جب یہ طاقتور ہو جائیں گے،جب یہ گھڑ چڑھے سوار بن جائیں گے اس وقت بھی یہ اپنی جانیںقربان کرنا اپنے لئے انتہائی باعث فخر سمجھیں گے اور ان میں اس قدر جوش ہو گا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑیاں مارتے اور انہیں منزل مقصود کی طرف دوڑاتے چلے جائیں گے.مگر دوسری طرف ان کے اخلاق ایسے اعلیٰ درجہ کے ہوں گے کہ وہ کبھی غا فل دشمن پر حملہ نہیں کریں گے، کبھی رات کو حملہ نہیں کریں گے، کبھی اچانک حملہ نہیں کریں گے.تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم اخلا ق کی پروا تک نہیں کرتے جب بھی کوئی مسلمان تمہارے قابو آجائے تم اسے مارنے پیٹنے لگ جاتے ہو مگر یہ اخلاق کو کسی حالت میں بھی نظر انداز نہیں کریں گے جب یہ طاقتور ہو جائیں گے، جب یہ گھڑ چڑھے سوار ہوجائیں گے تب بھی یہ فوراً حملہ نہیں کردیں گے بلکہ جب آئیں گے رات بھر انتظار کریں گے صبح کے وقت اگر تمہاری اذان کی آواز ان کے کانوں میں آئے گی تو یہ تم پر حملہ نہیں کریں گے اور اگر تمہاری اذان نہیں ہو گی تو اپنی اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچائیں گے تاکہ تم ہوشیار اور بیدار ہو جائو اور مقابلہ کے لئے تیار ہو کر باہر نکلو.غرض اس آیت میں مسلمانوںکے نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.پھر صرف اخلاق کی طرف ہی نہیں بلکہ اس آیت میں مسلمانوں کی دلیری کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ جو لوگ دشمن سے لڑتے ہیںوہ رات کو آگ بجھا دیا کرتے ہیںیہ نہیں کرتے کہ رات کو آگ روشن رکھیں اور دشمن کو
Page 134
اپنی موجودگی کا علم ہونے دیں مگر مسلمانوںکے متعلق فرمایا کہ وہ حملہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو آگ کو روشن رکھتے ہیںدشمن سے ڈر کر اسے بجھاتے نہیں.اسی طرح اس آیت میںمسلمانوں کی سخاوت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ عرب لوگ آگ جلانے سے سخاوت اور دلیری دونوں مراد لیا کرتے تھے.عرب شاعر اپنے مخالفوںکو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ ہماری قوم کی آگ جلتی رہتی ہے لیکن تمہاری قوم کی آگ بجھ جاتی ہے.اس میں دونوں طرف اشارہ ہوا کرتا تھا اس طرف بھی کہ ہم بہادر ہیں.ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اگر ہم نے آگ روشن کی تو دشمن کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیںاور اس طرف بھی کہ تم رات کو کھانا پکا کر آگ بجھا دیتے ہو تاکہ کوئی مسافر اس آگ کو دیکھ کر تمہارے پاس کھانا کھانے کے لئے نہ آجائے لیکن ہماری قوم مہمان نواز ہے ہماری آگ جلتی رہتی ہے اور جب کوئی مسافر آگ کو روشن دیکھ کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے کھانا کھلاتے ہیں.پس فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا میں دونوں باتیںبیان کی گئی ہیں.یہ بھی کہ ہم بہادر ہیں ہم روشنیوں کو ڈر سے بجھاتے نہیں بلکہ رات کو دلیری سے روشنی جلاتے ہیںاور یہ بھی کہ تم کَنُوْد ہو.بخل کی وجہ سے کسی کو کھانا کھلانا بھی پسند نہیں کرتے.مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی روشنیاں جلائے رکھتے ہیںتاکہ مسافر اور غرباء و مساکین وغیرہ آئیں اور کھانا کھائیں.یہ معنے ایسے ہیںجو کَنُوْد کے مقابلہ میںاس مقام پر زیادہ عمدگی سے چسپاں ہوتے ہیں.بعض مفسرین نے یہ بھی معنے کئے ہیں جو بہت لطیف ہیںکہ اللہ تعالیٰ نے رات کے لئے فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا کہا ہے اور صبح کے لئے فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا کہا ہے یعنی دونوں موقعوں پر جو چیز زیادہ ظا ہر ہونے والی تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے.رات کو اڑتی ہوئی گرد نظر نہیں آتی اور دن کو آگ کی روشنی نظر نہیں آتی پس مُوْرِيٰتِ قَدْحًا کو پہلے رکھ کر بتایا کہ وہ رات کو روشنیاں جلاتے ہیںاور دشمن کو للکار کر کہتے ہیںکہ دیکھ لو ہم آئے ہوئے ہیںاور صبح کو اپنے گھوڑوں سے گرد اڑاتے ہیںتاکہ وہ دور سے ہی دیکھ لیں کہ ہم آرہے ہیں.گویا ان دونوں آیتوں میںمسلمانوں کی جرأت اور ان کی بہادری کا اعلان کیا گیا ہے.فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًاۙ۰۰۴ پھر صبح ہی صبح حملہ کرنے والوں کی.حلّ لُغات.مُغِیْـرَات: اغارسے اسم فاعل مونث کا جمع کا صیغہ ہے اور اَغَارَ الرَّجُلُ کے معنے ہوتے ہیں اَتَی الْغَوْر وہ پانی کے چشمہ پر آیا یا کسی غار وغیرہ پر پہنچا اور اَغَارَ زَیْدٌ کے معنے ہوتے ہیں ذَھَبَ فِی
Page 135
الْاَرْضِ اس نے سفر کیا اور دور نکل گیا.اور صرف اَغَارَ کے معنے ہوتے ہیں اَسْـرَعَ وَدَفَعَ فِیْ عَدُ وِّہٖ وہ تیزی سے گیا اور اس نے اپنے گھوڑوں کو دشمن کی صفوں کے اندر ڈال دیااور اَغَارَ عَلَی الْقَوْمِ غَارَۃً وَ اِغَارَۃً وَ مَغَارًا کے معنے ہوتے ہیں دَفَعَ عَلَیْـھِمُ الْـخَیْلَ وَ اَخْرَجَھُمْ مِّنْ فَنَآءِھِمْ بِـھُجُوْمِہٖ عَلَیْـھِمْ وَ اَوْقَعَ بِـھِمْ انہوںنے حملہ کرکے دشمن کو ان کے صحنوں سے باہر نکالا اور پھر ان پر ٹوٹ پڑے (اقرب) پس مغیرات کے معنے ہوں گے (۱) دور دور نکل جانے والی جماعتیں (۲) اپنے گھوڑوں کو دشمنوں کی صفوں میں ڈالنے والی جماعتیں (۳)دشمن پر حملہ کرکے اسے ان کے صحن سے نکال دینے والی جماعتیں.تفسیر.مُغِیْـرَاتِ صُبْحًا میں مسلمانوں کی بہادری کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس وصف کو بیان کیا ہے کہ وہ رات کو کبھی حملہ نہیں کریں گے تا ایسا نہ ہو کہ دشمن نا واقفیت کی حالت میں مارا جائے.وہ صبح کے وقت حملہ کریں گے مگر حملہ ایسا شاندار ہوگا کہ دشمن فوراََاپنے گھروں سے نکل کر باہر آجائے گا.یہ کیسا بہادری کا طریق ہے جو اسلام نے بطور سنت جاری کیا.اس وقت انصاف وبہادری کی مدعی یورپین اقوام راتوں کو برابر دشمن پر حملہ کرتی ہیں اور غفلت میں حملہ کرنا اپنی خاص خوبی قرار دیتی ہیں.مگر اسلام بتاتا ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کریں گے وہ ہمیشہ صبح کے وقت حملہ کریں گے جو ثبوت ہوگا اس بات کا کہ مسلمان بہادر، نڈر اور رحم کرنے والے ہیں.مُغِیْـرَات کا لفظ بھی ان کی دلیری طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ اغارت کے ایک معنے یہ ہیں کہ دشمن پر حملہ کرکے اسے گھروں سے نکالنا اور پھر اس کا مقابلہ کرنا گویا گھروں میں گھس کر بچوں، عورتوں،بوڑھوں کو مارنا ان کا طریق نہ ہوگا بلکہ دشمن کے لڑنے والے لوگوں کو گھروں سے للکار کر نکالنا اور پھر ان کی صفوف پر حملہ کرنا ان کا طریق ہوگا جو ان کے دلیرانہ حملہ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا اسی طرح صُبْحًا میں یہ اشارہ ہے کہ وہ رات کو حملہ نہیں کرتے بلکہ جب صبح ہوتی ہے تو اس وقت حملہ کرتے ہیں تاکہ دشمن غافل نہ ہو اور اسے مقابلہ کا پوراموقع ملے.فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًاۙ۰۰۵ جس کے نتیجہ میں وہ اس(صبح کے وقت) میں غبار اڑاتے ہیں.حلّ لُغات.اَلنَّقْعُ.اَلنَّقْعُ : اَلْغُبَارُ: نَقْعٌ کے معنے غبار کے ہیں.نیز نَقْعٌ کے معنے اَلْاَرْضُ الْـحَرَّۃُ الطِّیْنِ یُسْتَنْقَعُ فِیْـھَا الْمَآءُ کے بھی ہیں یعنی وہ پتھریلی زمین جہاں پانی جمع کیا جاتا ہے اور نَقْعٌ مکہ کے
Page 136
پاس ایک مقام کا نام ہے.بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مقام منیٰ کا حصہ ہے حضرت علی ؓنے اسی وجہ سے وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا سے وہ حاجی مراد لئے ہیں جو عرفہ سے مزدلفہ کی طرف اور پھر مزدلفہ سے منیٰ کی طرف تیزی سے آتے ہیں.(فتح البیان سورۃ العادیات زیر آیت فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا) اور نَقْعٌ کے معنے اَلْقَاعُ کے بھی ہوتے ہیں یعنی صاف میدان اور نَقْعٌ کے معنے مَـحْبَسُ الْمَآءِ یعنی تالاب کے بھی ہیں (اقرب).نَقْعٌ کے معنے ابو عبیدہ نے آواز بلند کرنے کے بھی کئے ہیں اور لبید کا ایک شعر اس کی تائید میں پیش کیا ہے کہ انہوں نے بھی نَقْعٌ کا لفظ آواز بلند کرنے کے معنوں میں استعمال کیا ہے.حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک اثر منقول ہے جس میں انہوں نے نَقْعٌ کے معنے آواز بلند کرنے کے کئے ہیں.چنانچہ جب حضرت خالدؓ بن ولید کی وفات کی خبر آپ کو ملی توکسی نے کہا عورتیں وہاں رو رہی ہیں حضرت عمررضی اللہ عنہ نے کہاکیا بات ہے کہ عورتیں بیٹھی ہوئی رورہی ہیں اور کوئی نقع اور لقلقہ نہیںیعنی بلند آواز سے شور کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی.(اسد الغابۃ زیر خالد بن ولید) تفسیر.فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا میں بِہٖ کی ضمیر صبح کی طرف جاتی ہے یعنی فَاَثَرْنَ وَقْتَ الصُّبْحِ نَقْعًا وہ صبح کے وقت خوب غبار اڑائیں گے.یہاں بھی ایک لطیف بات بیان کی گئی ہے جو مسلمانوں کی شجاعت کی طرف اشارہ کرتی ہے اصل بات یہ ہے کہ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا سے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا رات کو اطمینان سے بیٹھ جانا، کھانا پکانا اور دشمن پر آتے ہی حملہ نہ کرنا شاید اس لئے ہے کہ قریب پہنچ کر ان کا جوش جاتا رہتا ہے.پہلے اگر ان سے جوش ظاہر ہوتا ہے اور وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑیاں مارتے اور ان کو دوڑاتے اور کداتے ہوئے میدان میں پہنچتے ہیں تو اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں پہنچتے ہی لڑائی نہیں کرنی پڑے گی بلکہ ہم اطمینان سے رات بھر آرام کریں گے پس ان کا وہ جوش جس کا ان کی طرف سے پہلے اظہار ہوتا ہے اس قابل نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے کیونکہ یہ جوش وہ ا س وقت دکھاتے ہیں جب دشمن سے مقابلہ ابھی دور کی بات ہوتا ہے قریب پہنچ کر ان کا تمام جوش سرد ہو جاتا ہے اور وہ دشمن پر حملہ کرنے کی بجائے کھانا پکانے میں مشغول ہو جاتے ہیں.اللہ تعالیٰ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا میں اس شبہ کا ازالہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے مسلمان صرف اسی وقت بہادری اور شوق نہیں دکھاتے جب دشمن دور ہوتا ہے بلکہ اس وقت بھی ان کا جوش تیز ہوتا ہے جب دشمن سامنے آجاتا ہے اور اس جوش سے حملہ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت بھی گردوغبار اڑا کر جوّ کو بھر دیتے ہیں.یہ قاعدہ ہے کہ صبح کے وقت شبنم سے گرد دبی ہوئی ہوتی ہے لیکن دوپہر اور شام کو گرد ڈھیلی ہو جاتی ہے اور ادنیٰ حرکت سے بھی اٹھ پڑتی ہے.پس صبح کے وقت گرد اڑانے سے جہاں ان کے طریق عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کبھی رات کو حملہ نہیں کرتے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے شوق جہاد کی
Page 137
طرف بھی اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ صبح کے وقت دشمن کو ہوشیار کرکے حملہ کرتے ہیں اور پھر اتنے جوش سے حملہ کرتے ہیں کہ صبح کی بیٹھی ہوئی غبار بھی اڑنے لگ جاتی ہے شام کے وقت تو اڑاہی کرتی ہے چنانچہ دیہات میں شام کے وقت جب جانور چراگاہوں سے واپس آتے ہیں تو گردوغبار سے تمام جوّ بھرا ہوا ہو تا ہے کیونکہ دن بھر کی دھوپ کی وجہ سے تمام ذرات خشک ہوکر ہوا میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صبح کے وقت یہ حالت نہیں ہوتی اس وقت شبنم پڑ کر غبار کو کم کر دیتی ہے.مگر فرماتا ہے مسلمان اتنی شدت اوراتنے جوش سے حملہ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت تمام جوّ گردو غبار سے اَٹ جاتا ہے حالانکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب گردو غبار سے جوّ صاف ہوتا ہے.فَاَثَرْنَ بِهٖ میں ضمیر سے مراد فعل اغارت فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا میں بِہٖ کی ضمیر بالمعنیٰ فعل اغارت کی طرف بھی جا سکتی ہے یعنی فَاَثَرْنَ بِـاِغَارَتِـھِمْ یا اَثَرْنَ بِفِعْلِ اِغَارَتِـہِمْ.اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وہ اغارت کے فعل کی وجہ سے گرداڑانے لگتے ہیں یعنی اغارت اس شدت سے کرتے ہیں کہ اس سے گرد اڑنے لگتی ہے.اس طرح یہاں باء سببیہ ہو جائے گی اور مطلب یہ ہوگا کہ اَثَرْنَ لِسَبَبِ اِغَارَتِـہِمْ نَقْعًا.نَقْعًا کی تنوین سے کثرت اور شدت مراد ہے یعنی اَثَرْنَ بِفِعْلِ اِغَارَتِـہِمْ نَقْعًا کَثِیْـرًا وہ بے انتہا گرد اڑاتے ہیں.یہ بات بھی مسلمانوں کے شوق اور ان کی دلیری پر دلالت کرتی ہے.اچانک حملہ کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں آہستہ چلو گرد نہ اڑائو ایسا نہ ہو کہ دشمن کو پتہ لگ جائے.مگر خالی گرد نہیں اڑاتے بلکہ بے انتہا گرد اڑاتے ہیں.باء اس جگہ ملابست کی بھی ہو سکتی ہے اس لحاظ سے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ بڑے ماہر فن ہیں کیونکہ بے تحاشاگھوڑا دوڑانا فی ذاتہٖ ایک فن ہے جو مہارت چاہتا ہے اور بے تحاشا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنا نیزہ سنبھال کر رکھنا تا کہ دشمن پر حملہ کیا جاسکے یہ دوسرا فن ہے.پس فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ وہ اغارت کے ساتھ ساتھ گھوڑے بھی بے تحاشا دوڑاتے اور اچھالتے چلے جاتے ہیں یعنی ایک طرف گھوڑے بھی دوڑاتے جاتے ہیں اور دوسری طرف لڑائی کا فن بھی قائم رہتا ہے.بسا اوقات ایک شخص گھوڑا تو دوڑا لیتا ہے لیکن لڑائی کے فن کو قائم نہیں رکھ سکتا.جب گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہو تو وہ نیزے کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتا اور نہ دشمن پر حملہ کرسکتا ہے بلکہ حملہ کرنے کے لیے اسے ٹھہرنا پڑتا ہے.مگر ایک دوسرا شخص ایسا ہو تا ہے جو گھوڑے کو بھی تیز دوڑاتا جاتا ہے اور لڑ تا بھی جاتا ہے.چنانچہ نیزہ بازی کے وقت عام طورپر دیکھا جاتا ہے کہ بعض سوار گھو ڑے کو دوڑاتے چلے آتے ہیں مگر جب میخ کے پاس آتے ہیں تو گھوڑے کو آہستہ کرلیتے ہیں تاکہ ان کا نشانہ خطا نہ جائے مگر جو اپنے فن میں ماہر ہوتے ہیں وہ اسی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میخ پر نیزہ مارتے ہیں اور اس کو اکھاڑ کر لے جاتے ہیں.جب
Page 138
ملک معظم ہندوستان میں آئے اس وقت جہاں اور کئی قسم کی کھیلیں ان کو دکھائی گئیں وہاں نیزہ بازی کے فن کا بھی ان کے سامنے مظاہرہ کیا گیا اس وقت بعض سوار تو اتنی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے کہ ذرا بھی ان کا گھوڑا نہ رکتا اور میخ کو اکھاڑ کر لے جاتے اور بعض میخ کے قریب پہنچ کر رہ جاتے.پھر بعض لوگ تو اپنے فن میں ایسے ماہر تھے کہ وہ بجائے بیٹھنے کے گھوڑے کی پیٹھ پر لیٹ کر اسے تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے آتے اور میخ اکھاڑ کر لے جاتے حالانکہ اس وقت معمولی سوار کے لئے بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے.غرض گھوڑے کو تیز دوڑانا اپنی ذات میں ایک فن ہوتا ہے اور پھر اسے تیز دوڑاتے ہوئے اپنے مفوضہ فرض کو کمال خوبی کے ساتھ سرانجام دینا یہ دوسرا فن ہوتا ہے.لڑائی میں صرف گھوڑے کو تیز دوڑانے کا فن کام نہیں آتا بلکہ اس دوسرے فن میں بھی مہارت کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے انسان دشمن پر بھی عمدگی سے حملہ کرسکے.فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی اَثَرْنَ مُلَابِسًا بِالْاِغَارَۃِ.مسلمانوں کی یہ حالت کہ ادھر دشمن پر حملہ کرنے کے لئے وہ بالکل تیار ہوتے ہیں اور ادھر وہ اپنے گھوڑوں کو انتہائی تیز دوڑا رہے ہوتے ہیں.گھوڑوں کا تیز دوڑناان کو فعل اغارت سے نہیں روکتا.یہ بات ان کے کمال درجہ کے شوق اور مہارت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ مسلمان رات اور دن جہاد کے لئے تیاریاں کرتے رہتے تھے جس کے نتیجہ میں انہیں جنگی فنون میں کامل مہارت حاصل ہو چکی تھی.چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں حبشیوں کو نیزوں کے کرتب دکھانے کی اجازت دی اور نہ صرف آپ نے ان کو بڑے شوق سے دیکھا بلکہ اپنے اہل بیت کو بھی دکھایا.(بخاری کتاب الصلٰوۃ باب اصحاب الحراب فی المسجد ) اسی طرح حدیثوں سے ثابت ہے کہ صحابہؓ ہمیشہ تیراندازی کی مشقیں کیا کرتے تھے.ایک دفعہ صحابہ ؓ کی دو پارٹیوں میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم بھی ایک پارٹی میں شامل ہوگئے.یہ دیکھ کر دوسری پارٹی نے اپنے تیر رکھ دیئے اور کہا یارسول اللہ یہ نہیں ہوسکتا کہ ہم اس پارٹی کا مقابلہ کریں جس میں آپ ہوں.(بخاری کتاب الجھاد والسیر باب التحریض علی الرمٰی) فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا میں مسلمانوں کے جنگی فنون میں ماہر ہونے کی طرف اشارہ غرض صحابہؓ اپنے آپ کو ہمیشہ جنگ کے لئے تیار رکھتے اور جنگی فنون میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی اسی مہارت کا ذکر فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا میں کرتا ہے اور فرماتا ہے آج مسلمان تمہیں کمزور اور بےکس نظر آتے ہیں مگر ہم بطور پیشگوئی یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ کمزور نظر آنے والے مسلمان ایک دن نہایت اعلیٰ درجہ کے ماہرفن ہوجائیں گے.اغارت ان کو تیز دوڑنے سے روک نہیں سکے گی اور تیز دوڑنا ان کو فعل اغارت سے نہیں
Page 139
روک سکے گا.وہ اغارت بھی کریں گے اور جوش وخروش سے گردوغبار بھی اڑاتے جائیں گے یعنی وہ کچے سوار نہیں کہ دوڑیں تو اغارت کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اوراغارت کریں تو دوڑ نہ سکیں بلکہ وہ دونوں کام ایک وقت میں کرتے ہیں گھوڑے تیز دوڑاتے ہوئے بھی اپنے جنگی فنون ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے یہ نہیں ہوتا کہ گھوڑے تیز دوڑارہے ہوں تو انہیں اپنی تلواروں اور نیزوں کا ہوش نہ ہو اور تلواریں اور نیزے سنبھالے ہوئے ہوں تو گھوڑوں کو تیز دوڑانے سے قاصر ہوں یہ دونوں باتیں ان میں بیک وقت پائی جائیں گی اور وہ اپنے فن میں ماہر ہوںگے.فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًاۙ۰۰۶ اور اسی (صبح کے وقت ) میں لشکر میں گھس جاتے ہیں.تفسیر.وَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں بِهٖ کی ضمیر نَقْعٌ کی طرف یا صُبْحٌ کی طرف فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں بِهٖ کی ضمیر نَقْعٌ کی طرف بھی جاتی ہے اور صُبْحٌ کی طرف بھی.اگر بِهٖ کی ضمیر نَقْعٌ کی طرف سمجھی جائے تو اس آیت کے معنے یہ ہوں گے کہ وہ دشمن تک برابر گرد اڑاتے چلے جاتے ہیں یعنی جب دشمن کے پاس پہنچتے ہیں تب بھی ان کا جوش وخروش کم نہیں ہوتا بلکہ جس طرح دور سے گھوڑےدوڑاتے اور خاک اڑاتے آتے ہیں دشمن کے پاس پہنچ کر بھی ان کی یہ حالت قائم رہتی ہے اور وہ خاک اڑاتے ہوئے بے جھجک اور بے رکے دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہوجاتے ہیں.اس آیت میں بھی ان کی بہادری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور درحقیقت صحابہؓ ایسے ہی نڈر اور بہادر تھے اور تاریخی واقعات ان کی اس بہادری پر شاہد ہیں.اگر فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں بِهٖ کی ضمیر صُبْحٌ کی طرف پھیری جائے تو اس آیت سے مراد یہ ہوگی کہ وہ صبح کے وقت دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں.اس میں پھر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ صحابہؓ کبھی اچانک حملہ نہیں کرتے بلکہ وہ اسی وقت حملہ کرتے ہیں جب دشمن ان کے مقابل میں نکل آئے.آج انگریزوںکو دیکھ لو، روسیوں کو دیکھ لو، امریکہ کے رہنے والوں کو دیکھ لو.سب کوشش کرتے ہیں کہ وہ یک دم سو تے دشمن پر حملہ کریںاور اس کو اپنی بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے مومن بندے ایسے نہیں ہوں گے وہ صبح کے وقت جائیں گے شور مچاتے جائیں گے اور اگر پھر بھی دشمن باہر نہیں نکلا تو وہ حملہ نہیں کریں گے بلکہ انتظار کریں گے یہاں تک کہ دشمن ان کے
Page 140
مقابلہ میں اپنے گھروں سے نکل آئے اور یہ مضمون لفظ جَـمْعٌ سے نکلتا ہے کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں کہ اس میں عورت،بوڑھا،بچہ سب شامل ہوں بلکہ فرمایا کہ جَـمْعٌ یعنی لشکر میں گھس جاتے ہیںیعنی ان کا حملہ اکے دکے کمزور ضعیف پر نہیں ہوتا ہمیشہ دشمن کے مجتمع لشکر پر حملہ کرتے ہیں.پس فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں دونوں طرف اشارہ ہے اس طرف بھی کہ وہ حملہ کرتے وقت اس بات کو مدّ ِنظر رکھتے ہیں کہ رات کے وقت حملہ نہ ہو بلکہ صبح کو ہو اور حملہ ایسی حالت میں ہو کہ جب جَمْعًا یعنی دشمن کا لشکر ان کے سامنے کھڑا ہو.گویا ان کے گھروں سے نکال کر وہ مقا بلہ کریں گے سوتے دشمن پر اچانک حملہ نہیں کریںگے.فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں مسلمانوں کی شیدائیت اور قربانی کی طرف اشارہ دوسرے جب دشمن ان کے مقابل پر آتا ہے تب بھی ان کا جوش و خروش قائم رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ دور سے تو جوش و خروش دکھاتے جائیں اور دشمن کے پاس پہنچ کر ان کے جوش سرد ہو جائیں.غرض بِهٖ کی ضمیر اگر صُبْحٌ کی طرف لے جائو تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ صبح کو وہ ایسے وقت حملہ کریں گے جب دشمن کا لشکر ان کے مقابلہ میں جمع ہو جائے اور اگر بِهٖ کی ضمیر نَقْعٌ کی طرف لے جائو تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ ان کا جوش دشمن کو دیکھ کر ڈھیلا نہیں ہوتا بلکہ جب دشمن کو وہ اپنے مقابل میں صفیں باندھے کھڑا دیکھتے ہیں تو ان کا جوش اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ حملہ کرتے ہوئے اس کی صفوں کے اندر جا گھستے ہیں.ان میں سے ایک معنوں میں ان کے اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسرے معنوں میں ان کی اسلام کے لئے شیدائیت اور قربانی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے.فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں مسلمانوں کے جلد دشمنوں پر غالب آجانے کی طرف اشارہ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں اگر بِهٖ کی ضمیر صُبْحٌ کی طرف ہو تو اس کے ایک اور بھی لطیف معنے ہو جائیں گے یعنی اس کے صرف اتنے معنے نہیں ہو ں گے کہ صحابہؓ کبھی رات کو حملہ نہیں کرتے بلکہ اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی پایا جاتا ہے کہ وہ صبح ہی صبح دشمن کی صفوں کو توڑ دیتے ہیں.ابن جنی نے بھی یہی معنے کئے ہیںوہ کہتے ہیں مَیَّـزْنَ بِہٖ جَـمْعًا اَیْ جَعَلْنٰہُ شَطْرَیْنِ اَیْ قِسْمَیْنِ وَشِقَّیْنِ (روح المعانی زیر سورۃ العادیات ) گویا ان کا حملہ بڑا کامیاب ہوتا ہے زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتے اور ان کو پوری طرح مغلوب کر لیتے ہیں.وَسَطْنَ کا لفظ بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ خالی سامنے کھڑا ہونے سے وَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا کے الفاظ صادق نہیں آسکتے.یہ الفاظ اسی صورت میں صادق آسکتے ہیںجب دشمن کی صفوں کو توڑ کر ان کے اندرداخل ہوجانا اس کے مفہوم میں شامل ہو.اور درحقیقت اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ وہ کفار کے لشکر میں گھس جاتے اور ان کی صفوں کو
Page 141
توڑ کر پراگندہ کر دیتے ہیں.جرنیل کے فرائض میں سے یہ ایک اہم ترین فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دے کیونکہ جب دشمن صفوں کو توڑ کر اندر داخل ہو جائے تو فوج پراگندہ ہو جاتی ہے اور متحدہ مقابلہ کی قوت کو کھو بیٹھتی ہے.چنانچہ ہمیشہ ماہر فن جرنیل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دشمن کے شدید حملہ کے باوجود اپنی صفوں کو قائم رکھے لیکن کبھی کبھی اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ (الانفال:۱۷)کے مطابق دشمن کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ افسر سمجھتا ہے کہ گو مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں واپس لوٹ کر اس پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہوںمگر اس وقت حالت ایسی ہے کہ دو یا چار یا دس منٹ کے لئے صفوںکے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس وقت ماہر فن جرنیل کا یہ طریق ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفیں پیچھے کر لیتا ہے انگریزی میں اسے آرڈرلی رٹریٹ یعنی باقاعدہ پیچھے ہٹنا کہتے ہیںمطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی صفوں کو قائم رکھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا.پس صفوں کو قائم رکھنا جنگ کے ضروری اصول میں سے ہے.اسی طرح حملہ کرنے والوں کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح دشمن کی صفوں میں گھس جائیں.انگریزی میں اس طرح داخل ہونے کی کوشش کو سپیئر ہیڈspearhead کہتے ہیں.جب دشمن کی صفوں میں مقابل کا لشکر داخل ہوجائے تو دشمن پراگندہ ہو جاتا ہے اور اس کا جرنیل اپنے لشکر کو کوئی حکم نہیں دے سکتا.ایک طرف والوں کو حکم دے تب بھی اور دوسری طرف والوں کو حکم دے تب بھی،درمیان میں غنیم کھڑا ہوتا ہے اور وہ آسانی سے ان کی تمام تدابیر کا ازالہ کر سکتا ہے.غرض دشمن کے دبائو کے وقت بچائو کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا تو جرنیل اتنا ہوشیار ہو کہ وہ فوراً اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لے اور یا پھر ان میں اتنی اخلاقی قوت باقی ہو کہ اگر جرنیل فوج کے انتشاراور اس کی پراگندگی کی حالت میں بھی حکم دے کہ اتنا پیچھے ہٹ جائو تو فوج اتنا پیچھے ہٹ جائے ورنہ اس کی شکست میںکوئی شبہ نہیں ہوتا.پس فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ صبح ہی صبح دشمن کی صفوں میں گھس بھی جاتے اور اسی وقت ان کو توڑ پھوڑ کر بھی رکھ دیتے ہیںدیر ہی نہیں لگتی.ان معنوں سے اس شبہ کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے کہ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا میں یہ پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ وہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں اور اب فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صبح ہی صبح دشمن پر حملہ کرتے ہیں.جب صبح کے وقت حملہ کرنے کا ذکر پہلے بھی آچکا تھا تو دوبارہ صبح کے وقت دشمن کی صفوں میں ان کے داخل ہونے کا کیوں ذکر کیا گیا ہے اور یہ تکرار اپنے اندر کیا حکمت رکھتا ہے؟سو اس کا جواب یہ ہے کہ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا کے بعد فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں وہی مضمون بیان نہیں کیا گیا بلکہ ایک نیا مضمون بتا یا گیا ہے.
Page 142
جیسا کہ مختصراً پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا اور فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے حملہ اور ان کی فتح میں کوئی لمبا وقت صرف نہیں ہوتا.ان کا حملہ بھی صبح کے وقت ہوتا ہے اور ان کی فتح بھی صبح کے وقت ہوتی ہے یعنی ادھر حملہ کرتے ہیں اور ادھر دشمن کو چند گھڑیوں میں ہی مغلوب کر لیتے ہیں.فرماتا ہے کہ تم مسلمانوں کی موجودہ کمزور حالت کو دیکھ کر یہ مت خیال کرو کہ ان کا مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا.تمہیں آج یہ بے شک کمزور دکھائی دیتے ہیںلیکن درحقیقت یہ ایسے دلیر اور بہادر ہیںکہ جب ہمارے حکم کے ماتحت یہ تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائیں گے تو ادھر حملہ کریں گے اور ادھر منٹوں میں اپنا سارا کام ختم کر کے دشمن کو مغلوب کر لیں گے اور فتح و کامرانی کا پرچم لہرانے لگیں گے.چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس قدر غزوات ہوئے ان میں قلعہ بند جنگوں کے سوا کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جو چند گھنٹوں میں ختم نہ ہوگئی ہو.احزاب کی جنگ بے شک لمبی ہوئی مگر اس لئے کہ وہاں صحابہؓ کو خود یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے حملہ نہیں کرنا صرف دفاع کرنا ہے.خیبر کی جنگ لمبی ہوئی مگر وہ قلعہ بند جنگ تھی.بنو قریظہ سے جو جنگ ہوئی وہ بھی قلعہ بند جنگ تھی ان کو چھوڑ کر جتنی بھی جنگیں ہوئیںہیںان میں سے کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس کا چند گھنٹوں میں فیصلہ نہ ہو گیا ہو.اسی طرح آپ نے جو سریے بھجوائے وہ بھی اسی طرح حیرت انگیز طور پر کامیابی حاصل کرکے واپس آتے رہے.یہ ایک ایسی غیر معمولی بات ہے جسے دیکھ کر حیرت آتی ہے کہ ایک جنگ نہیں دو جنگیں نہیں بیس سے زیادہ جنگیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں مگر تمام جنگیں ایسی ہیں جو دنوں کی بجائے گھنٹوں بلکہ منٹوں میں ختم ہوگئیں.بدر کی جنگ بہت بڑی جنگ تھی مگر اس کا کتنی جلدی فیصلہ ہوگیا.حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ کہتے ہیں میرے دائیں بائیںدو انصاری لڑکے کھڑے تھے اور میں اپنے دل میں افسوس کر رہا تھا کہ آج مجھے اپنے دل کے حوصلے نکالنے کا کوئی موقع نہ ملا کیونکہ میرے دائیں بائیں پندرہ پندرہ برس کے دو انصاری لڑکے کھڑے ہیں اگر ماہر فن سپاہی میرے ارد گرد ہوتے تو میں نڈر ہو کر حملہ کر سکتا اور سمجھتا کہ میری پیٹھ بچانے والے موجود ہیں.وہ کہتے ہیں ابھی یہ خیال میرے دل میں پیدا ہی ہوا تھا کہ مجھے دائیں طرف سے کہنی لگی میں نے مڑ کر دیکھا تو دائیں طرف کے انصاری لڑکے نے آہستگی سے میرے کان میں کہا چچا وہ ابو جہل کون سا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ آج اس سے بدلہ لوں.وہ کہتے ہیں ابھی میں اس کے سوال کا کوئی جواب دینے نہیں پایا تھا کہ مجھے بائیں طرف سے کہنی لگی.میں نے مڑ کر دیکھا تو بائیں طرف کے انصاری لڑکے نے آہستگی سے جھک کر میرے کان میں کہا چچا وہ ابوجہل کون سا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ آج اس سے
Page 143
بدلہ لوں.حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کہتے ہیںکہ باوجود تجربہ کار جرنیل ہونے کے میرے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا تھا کہ میں ابوجہل کو مار سکوں گا.اس لئے جب ان دو انصاری لڑکوں نے یہ سوال کیا تو میں حیران رہ گیا کہ میں اپنے دل میں کیا خیال کر رہا تھا اور انہوں نے مجھ سے کیا سوال کر دیا.میں نے اپنی انگلی اٹھائی اور کہا وہ جو قلب لشکر میں کھڑا ہے جس کے آگے دوجرنیل ننگی تلواریں لئے پہرہ دے رہے ہیں وہ ابو جہل ہے.وہ کہتے ہیںابھی میری انگلی نیچے نہیں ہوئی تھی کہ جس طرح عقاب چڑیا پر حملہ کرتا ہے وہ دونوں لڑکے تیزی کے ساتھ گئے اور پیشتر اس کے کہ وہ ننگی تلواریں سونت کر پہرہ دینے والے جرنیل سنبھلتے انہوں نے ابو جہل کو مار گرایا حالانکہ ان جرنیلوں میں سے ایک ابوجہل کا اپنا لڑکا تھا.جب ابوجہل مارا گیا جو فوج کا کمانڈر تھا تو جنگ درحقیقت ختم ہو گئی بعد میں جو جنگ ہوئی اس کی حیثیت صرف دفاعی رہ جاتی ہے مگر وہ جنگ بھی چند گھنٹے میں ختم ہو گئی.( بخاری کتاب الـجھاد والسیر باب فضل من شھد بدرًا ) اسی طرح احد کی جنگ میں ہوا بے شک بعدمیں مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے دشمن کچھ نقصان پہنچانے میں بھی کامیاب ہوگیا مگر بہر حال ایک دو گھنٹہ میں ہی مسلمانوں نے دشمن کو مغلوب کر لیا تھا حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓکے زمانہ میں بعض دفعہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس دن لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور لڑائیاں بھی ایسی جو قلعہ بند نہیں تھیں کھلے میدانوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا تھا اور متواتر کئی کئی دن تک چلا جاتا تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چند سو ایک ہزار کے مقابلہ میں آتے تھے یا دو ہزار دس ہزار کے مقابلہ میں کھڑ ے ہوتے تھے اور چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جاتا تھا.تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی تو ایسی نہیں ملتی کہ جنگ میں شام کے وقت یہ کہا گیا ہو کہ اب لڑائی بند ہو صبح سے پھر جنگ کی جائے گی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب لڑائیاں گھنٹوں اور منٹوں میں ختم ہو جاتی تھیں.پس فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا انکشاف فرماتا ہے کہ مسلمان غیر معمولی طاقت رکھنے والے ہوں گے.دشمن کی صفوں میں صبح صبح گھس جائیں گے اور ابھی صبح ختم نہیں ہو گی کہ ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی.کوئی شخص ایک جنگ بھی تاریخ میں سے ایسی پیش نہیں کر سکتا جس میں لڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دوسرا دن آگیا ہو بلکہ ابھی شام بھی ہونے نہیں پاتی تھی کہ لڑائی ختم ہو جاتی تھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستائیس۲۷ غزوات میں حصہ لیا اور اڑتیس ۳۸سرایا ہیںجو مختلف مواقع پر آپ نے بھجوائے مگر کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی جب شام کو دشمن سے کہا گیا ہو کہ اب ٹھہر جائو صبح پھر تم سے جنگ کی جائے گی.مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی صحابہ ؓ تھے جو پندرہ پندرہ بیس بیس دن تک لڑائی کرتے چلے جاتے تھے تب انہیں فتح حاصل ہوتی تھی.
Page 144
اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌۚ۰۰۷ انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی نا شکرا ہے.حلّ لُغات.اَلْکَنُوْدُ.اَلْکَنُوْدُ: اَلْکَفُوْرُ یَسْتَوِیْ فِیْہِ الْمُذَکَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ.کَنُوْد کے معنے کَفُوْر کے ہیں یعنی ایسا انسان جو نا شکرا ہو اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کرنے والا ہو.یہ لفظ مرد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لئے بھی.یعنی عورت کا ذکر ہو تو کہیں گے اَلْاِمْرَأَ ۃُ الْکَنُوْدُ.اورمرد کا ذکر ہو تو کہیں گے اَلرَّجُلُ الْکَنُوْدُ اسی طرح کَنُوْد کے ایک معنے اَلْکَافِرُ کے بھی ہیں کَنُوْد سے مراد تو ایسا شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کرنے والا تھا اور کافر سے مراد ایساشخص ہے جس پر دینی اصطلاح میں کفر کا اطلاق ہوتا ہو.کَنُوْد کے ایک معنے اَللَّوَّامُ لِرَ بِّہٖ کے بھی ہیںیعنی اپنے رب پر الزام لگانے والا اور اسے ملامت کرنے والا.(اقرب) بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کی ہتک کرتے ہیںکہتے ہیں خدا نے ہمیں کیا دیاہے سب کچھ اس نے امیروں کو دے دیا ہے.ہم اس کا کیوں شکر ادا کریں.ہم کیوں نمازیں پڑھیں.ہمارے سر پر اس نے کون سا احسان کیا ہے غریب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں امیر نمازیں پڑھتے پھریںاور امیر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری صحتیں کمزور ہیںطاقت اور توانائی تو اس نے غریبوں کو دے دی ہے ہم اس کا کیوں شکر ادا کریں.غرض امیر ہوتا ہے تب بھی اور غریب ہوتا ہے تب بھی وہ ہر وقت خدا تعالیٰ پر عیب لگاتا رہتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ خدا تعالیٰ نے کون سا سلوک کیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروںاسی طرح کَنُوْد کے ایک معنے اَلْبَخِیْلُ کے بھی ہیں یعنی ایسا شخص جو اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے اور کَنُوْد کے معنے عاصی اور گناہ گا ر کے بھی ہیں اور کَنُوْد کے ایک معنے اَلْاَرْضُ لَا تَنْبُتُ شَیْئًا کے بھی ہیں یعنی ایسی زمین جس میں سے کچھ پیدا نہیں ہوتا یُقَالُ ھٰذِہٖ اَرْضٌ کَنُوْدٌ.چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کَنُوْد ہے اور اس کے معنے یہ ہوتے ہیںکہ اس میں سے کچھ اگتا نہیں.پھر کَنُوْد اسے بھی کہتے ہیںجو اکیلا کھائے اور اپنے مال کو خرچ نہ کرے اور اپنے غلام کو مارتا رہے چنانچہ لغت میں لکھا ہے اَلْکَنُوْدُ مَنْ یَّاْکُلُ وَحْدَہٗ وَ یَـمْنَعُ رِفْدَہٗ وَیَضْـرِبُ عَبْدَہٗ (اقرب) گویا کمینہ کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.کھانا کھانے بیٹھے تو اکیلا کھائے گا کسی اور کو اپنے کھانے میں شریک نہیں کرے گا خدا تعالیٰ نے روپیہ دیا ہو تو اسے خرچ نہیں کرے گا.رِفْدٌ کے معنے دراصل عطا کے ہوتے ہیں.پس یَـمْنَعُ رِفْدَہٗ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے پاس روپیہ ہوتا ہے مال و دولت ہوتی ہے مگر وہ کسی کو دیتا نہیں وَیَضْـرِبُ
Page 145
عَبْدَہٗ اور بہادری یہ جتاتا ہے کہ غلام کو مارنے لگ جاتا ہے.گویا اس کے معنے کمینہ،بخیل اور بزدل انسان کے ہیں.کمینہ کا مفہوم اکیلے کھانا کھانے میں آجاتا ہے کیونکہ کھانا ایسی چیز ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی کھا رہا ہو تو دوسرے کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ آیئے کھانا کھا لیں.مگر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اکیلا چھپ کر کھاتا ہے اور کسی دوسرے کو اپنے کھانے میں شریک کرنا پسند نہیں کرتا.پھر ساتھ ہی بخیل بھی ہے کہ مال اس کے پاس موجود ہوتا ہے مگر کسی کو دینا پسند نہیں کرتا اور پھر طُرّہ یہ کہ وہ بزدل بھی ہے اپنی ساری بہادری غلاموں یا عورتوں پر جتاتا ہے اور کہتا ہے مار کر تمہارے دانت توڑ دوں گا لیکن اگر کوئی طاقت ور سامنے آجائے تو سر جھکا لیتا ہے.ان معنوں میں سے آخری معنے حدیث میں بھی استعمال ہوئے ہیں.چنانچہ ابن ابی حاتم اور ابن جریر دونوں کی رو ایت ہے ابی امامہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْکَنُوْدُ الَّذِیْ یَّاْکُلُ وَحْدَہٗ وَیَضْـرِبُ عَبْدَہٗ وَیَـمْنَعُ رِفْدَہٗ (تفسیر ابن کثیر سورۃ العادیات زیر آیت اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ) کَنُوْد وہ ہے جو اکیلا کھانا کھائے،اپنے غلام کو مارے پیٹے اور اپنی عطا کو روک لے.میں نے اس سے استنباط کرتے ہوئے کہا ہے کہ کَنُوْدُ وہ ہے جو کمینہ ہو کیونکہ کمینہ انسان ہی کھانا کھانے لگے تو کسی اور کو اس میں شریک کرنا پسند نہیں کرتا.اسی طرح کَنُوْد وہ ہے جو بزدل ہو اپنے غلاموں یا عورتوںکو مارتا پیٹتا رہتا ہو بہادر کے سامنے اپنی آنکھیں اونچی نہ کر سکتا ہو اور پھر کَنُوْد وہ ہے جو بخیل ہو اور اپنی عطا کو روک لے.لیکن میں سمجھتا ہوں اَلْکَنُوْدُ الَّذِیْ یَّاْکُلُ وَحْدَہٗ میں صرف اس کی کمینگی کی طرف ہی اشارہ نہیں بلکہ اس کے ایک معنے متکبر کے بھی ہیں کیونکہ متکبر آدمی بھی دوسرے کو اپنے ساتھ کھلانا پسند نہیں کرتا.کہتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں.اسی طرح اکیلا کھانا کھانے کے ایک اور معنے بھی ہو سکتے ہیںاور وہ یہ کہ وہ صرف اپنے طبقہ کے لوگوں کو دعوتوںوغیرہ میں شریک کرتا ہے نچلے درجہ کے لوگوں کو کھانے کے لئے نہیں بلاتا.اس صورت میں مَنْ یَّاْکُلُ وَحْدَہٗ کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ وہ اکیلا کھاتا ہے کسی دوسرے کو شامل نہیں کرتا بلکہ اس کے معنے یہ ہو جائیں گے کہ وہ صرف اپنے جیسے لوگوں کو جو اس کے طبقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کھانے میں بلا لیتا ہے لیکن اور لوگوں کی پروا نہیں کرتا.دعوت کرتا ہے تو بڑے بڑے رئیسوں تک اس کی دعوت محدود ہوتی ہے عوام الناس کو جن میں اکثریت غرباء اور مساکین کی ہوتی ہے پوچھتا تک نہیں.یہ معنے ایسے ہیں جو کفار پر نہایت عمدگی کے ساتھ چسپاں ہوتے ہیںکیونکہ عرب میں بڑی کثرت سے رواج تھا کہ دعوتوں میں امراء وغیرہ کو تو بلا لیا جاتا مگر غرباء کو دعوتوں میں نہ بلایا جاتا تھا ہاں کھانا ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا.اگلی آیت بھی ان معنوں کی تائید کرتی ہے کیونکہ اس میں مضمون یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اسے غرباء کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا مشکل نظر آتا تھا تو روپیہ پیسہ سے تو
Page 146
وہ ان کی مدد کر سکتا تھا مگر وہ یہ بھی نہیں کرتا.لغت کی کتاب تعریفات میں لکھا ہے ھُوَ الَّذِیْ یَعُدُّ الْمَصَائِبَ وَیَنْسَی الْمَوَاھِبَ (اقرب) کَنُوْد وہ ہوتا ہے جو مصیبتیں گنتا رہتا ہے کہ فلاں مصیبت مجھے پہنچی.فلاں تکلیف مجھے پیش آئی وَیَنْسَی الْمَوَاھِبَ اور انعامات کو بھول جاتا ہے.اسے یہ تو یاد رہتاہے کہ فلاں وقت میں اپنے دوست کے پاس گیا اور اس سے فلاں چیز مانگی جس کے دینے سے اس نے انکار کر دیا مگر وہ دس ہزار چیزیںجو اس نے مختلف اوقات میں دی ہوتی ہیں اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور وہ کبھی ان کا ذکر تک نہیں کرتا.تفسیر.وَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا میں جَمْعًا سے مراد کنود انسان یہاں اَلْاِنْسَان سے ہرانسان مراد نہیں بلکہ یہ اشارہ ہے وَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا والے انسانوں کی طرف.یعنی جس جمع پر انہوں نے حملہ کرنا تھا وہ جمع جن انسانوں پر مشتمل ہے وہ اس جگہ مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جن پر یہ مسلمان حملہ کریں گے ان کا اپنے رب کے ساتھ اس اس طرح کا معاملہ ہے ایک تو وہ کافر ہیںخدا تعالیٰ کی باتوں کا انکار کررہے ہیں اور دوسرے وہ سخت ناشکرے ہیں.خدا تعالیٰ کے احسانات کی وہ ذرا بھی قدر نہیں کرتے.خدا تعالیٰ نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ ایک ریتلے علاقہ میں وہ چاروں طرف سے رزق جمع کر کے لاتا اور ان کو کھلاتا پلاتا ہے مگر ان کی حالت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کے ان انعامات کے شکر گذار ہوتے اور جب اس کی طرف سے کوئی پیغام آتا تو وہ دوڑتے ہوئے اس پر عمل کرتے الٹا خدا تعالیٰ کی باتوں کاانکار کر رہے ہیں غریبوں کو کھانا تک نہیں کھلاتے اور غلاموں پر ظلم وستم کے پہاڑ گرارہے ہیں.چنانچہ پہلی سورتوں میں مکہ والوں کی اس حالت کا ذکر آچکا ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے.صدقہ وخیرات کی طرف توجہ نہیں کرتے.یتامیٰ ومساکین کی خبر گیری نہیں کرتے بلکہ جو کچھ آئے اسے عیاشی میں لٹا دیتے ہیں.اب کَنُوْد کہہ کر ان کی اس حالت کی طرف بھی اشارہ کردیا کہ انہیں دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم بڑے بہادر ہیں مگر حالت یہ ہے کہ غلاموں کو ہر وقت مارتے پیٹتے رہتے ہیں گویادناء ت اور کمینگی کے ساتھ بزدلی بھی ان میں کمال درجہ کی پائی جاتی ہے کہ کسی طاقتور کا مقابلہ کرنے کی بجائے کمزوروںپر اپنا غصہ نکالتے ہیں.بلالؓ قابوآئے تو ان کو مارنے پیٹنے لگ گئے لیکن جب ابوذر غفاریؓ کو مارا تو کسی نے ان سے کہہ دیا کہ جانتے ہو یہ شخص بنو غفار میں سے ہے جو تمہارے تجارتی راستہ پر آباد ہیں اگر ان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ تمہارا راستہ روک دیں گے یہ سننا تھا کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے اور انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا تا ایسا نہ ہو کہ ان کی روٹی بند ہو جائے (بخاری کتاب المناقب باب اسلام ابی ذرٍّ) لیکن بلالؓ یا کوئی اور ایسا غلام سامنے آتا جس کی پشت پر کوئی قوم نہ تھی تو
Page 147
اسے پیٹنے لگ جاتے.پس فرماتا ہے یہ بھی کوئی انسان ہیں.متکبر یہ ہیں،بخیل یہ ہیں،کمینہ یہ ہیں،بزدل یہ ہیں، کمزور ملے تو اس پر ظلم کرتے ہیں، غریب ملے تو اسے کھانا نہیں کھلاتے.روپیہ پاس ہو تو کسی پر خرچ نہیں کرتے.جب ان کی حالت یہ ہے تو خدا تعالیٰ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ یہ لوگ ملک پر حاکم رہیںیہ تو سزا کے قابل ہیںچنانچہ آج یہ جن غلاموں کو مارتے اور بڑے فخر سے اس کا اظہار کرتے ہیںہم انہی غلاموںکو ایک دن گھوڑوں پر چڑھا کر لائیں گے اور پھر ان کو بتائیں گے کہ بہادر کیسے ہوتے ہیں.یہ تو اپنی تمام بہادری صرف اس بات میں سمجھتے ہیں کہ غلام ملے تو ان کو مار پیٹ لیا یا کسی عورت کی شرمگاہ میں نیزہ مارااور اس کو ہلاک کردیا یاکوئی بےکس مسلمان قابو آگیاتو اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی اور پھر ان اونٹوں کو مخالف اطراف میں دوڑا کر اس کو ٹکرے ٹکرے کر دیا یا یہ بڑی بہادری اس بات میں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سینہ پر گرم گرم پتھر رکھے یا انہیں مکہ کے گلی کوچوں میں کھردرے اور نوکیلے پتھروں پر گھسیٹا اور ان کو لہو لہان کر دیا.مگر ایک دن آنے والا ہے جب ہم ان کَنُوْد کو یہ بتائیں گے کہ بہادر کیسے ہوتے ہیں اور بہادری کس چیز کا نام ہے.دیکھو چونکہ یہ مکی سورۃ ہے اور دشمن کو خواہ مخواہ اشتعال دلانا مقصود نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں بیان کرتے ہوئے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس کے دوسرے معنے بھی ہو سکتے ہیں تاکہ ان کی طبیعت میں اشتعال پیدا نہ ہو اور ان کا ذہن دوسرے معنوں کی طرف چلا جائے ورنہ در حقیقت اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ سے کفار مکہ ہی مراد ہیں اور مراد یہ ہے کہ کفار خدا تعالیٰ کے نا شکرے ہیں خدا تعالیٰ کی مدد ان کو کہاں مل سکتی ہے.چونکہ یہ اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں،غریبوںپر ظلم کرتے ہیں،فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے،صدقہ وخیرات کو ایک عبث فعل قرار دیتے ہیں اس لئے ایک دن بطور سزا ہم مسلمانوں سے ان پر حملہ کرائیں گے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ برے اعمال کا کیسا عبرتناک انجام ہوا کرتا ہے.وَ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌۚ۰۰۸ اور وہ یقیناً اس پر (اپنے قول اور فعل سے) گواہی دے رہا ہے.تفسیر.اس آیت میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں میں ایک طرف تو مذکورہ بالا عیوب پائے جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ ان عیوب پر فخر کرتے ہیں.غلاموں یا عورتوں کو مارنا کتنی قابل شرم حرکت ہے مگر ان کی حالت یہ ہے
Page 148
کہ غلاموں کو مارتے ہیںاور پھر فخر کرتے ہیںحالانکہ اگر انسان میں ذرا بھی شرم وحیا کا مادہ ہو اور وہ کسی بچے کو مار رہا ہو یا غلام کو بے دردی سے پیٹ رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے کہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ ہزار بہانے بنانے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ خرابی کی تھی وہ خرابی کی تھی تا اس کی کمینگی پر پردہ پڑ جائے.مگر فرماتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ بجائے نادم اور شرمندہ ہونے کے فخر کرتے ہیںاور کہتے ہیں آج ہم نے غلاموں کو خوب مارا.آج ان کو پتھروں پر خوب گھسیٹا، آج ان کو گلی کوچوں میں خوب لتاڑا.گویا یہ کمبخت انسان ایک تو گندہ اور ناپاک ہے اور پھر اپنی گندگی پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ عیب کیا ، میں نے وہ عیب کیا.اسی طرح وہ غریبوں کو نہیں دیتا.جب پوچھا جائے تو کہتا ہے اَھْلَکْتُ مَالًا لُّبَدًا (البلد:۷) میں نے تو ڈھیروں ڈھیر روپیہ خرچ کیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ (البلد:۸) کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا یا لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیںکہ وہ جو کچھ کررہا ہے عزت نفس کے لئے کر رہاہے قوم کی بہبودی یا غرباء کی ترقی کا خیال اس کے ان اخراجات کا محرک نہیںبے شک وہ دن میں کئی کئی اونٹ ذبح کر دیتا ہے مگر اس لئے نہیں کہ بھوکوں کو کھانا ملے بلکہ اس لئے کہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو.غرض نہ صرف اس میں متعدد عیوب پائے جاتے ہیںبلکہ اِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ وہ ان عیوب پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو مجھ میں یہ یہ باتیں پائی جاتیں ہیں.یا مثلاً روپیہ تو پاس ہو ا لیکن اگر کوئی شخص فاقہ زدہ ہوا تو اس کو کھانا نہ کھلایا.قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب کفار سے یہ کہاجاتا کہ غریبوں کی مدد کرو اور اپنے مال میں سے صدقہ وخیرات دو تو وہ جواب میں کہتے ہیںکہ ان کی مدد کرنا تو خدائی منشا کی مخالفت کرنا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسےلوگوں کے متعلق فرماتا ہے وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ١ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗۤ١ۖۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ( یٰسٓ:۴۸) جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلائو اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو وہ کہتے ہیںہم ان کو کیوں کھانا کھلائیںہم تو اللہ والا فعل کر رہے ہیںاللہ نے ان کو نہیں کھلایا ہم نے بھی ان کو نہیں کھلایا.تم ایسے لوگوں کو کیوں کھلاتے ہو جن کو خود اللہ تعالیٰ نے بھوکا رکھنا پسند کیا ہے.اس آیت میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ وہ ایک طرف تو غریبوں کو کھانانہیں کھلاتے تھے اور پھر اپنی اس کمینگی اور بے حیائی پر شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ والا فعل کر رہے ہیں تم ہمیں مورد الزام کس طرح قرار دے سکتے ہو.
Page 149
وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌؕ۰۰۹ اور وہ یقیناً (باوجود اس کے)مال کی محبت میں بہت بڑا تیز ہے.حلّ لُغات.اَلْـخَیْـرُ.اَلْـخَیْـرُ.خَیْرٌ کے معنے ہوتے ہیں وِجْدَانُ الشَّیْءِ عَلٰی کَمَالَاتِہِ الَّائِقَۃِ کسی چیز میں جو کمالات پائے جانے چاہئیںان تمام کمالات کے ساتھ جب کوئی چیز ہو تو اس کو عربی زبان میں خَیْرٌ کہتے ہیںاور خَیْرٌ کے معنے گھوڑوں کے بھی ہوتے ہیںاور خَیْرٌ کے معنے اس چیز کے بھی ہوتے ہیںجس میں بہت سی خیر پائی جائے یعنی بہتر سے بہتراور خَیْـرٌ مطلق مال کو بھی کہتے ہیں (اقرب) شَدِیْدٌ کے معنے شُـجَاعٌ.بَـخِیْلٌ.قَوِیٌّ.رَفِیْعُ الشَّاْنِ اور مضبوط کے ہوتے ہیںاور کنایۃً شَدِیْدٌ کا لفظ متکبر اور عظمت پسند کے معنوں میںبھی استعمال ہوتا ہے اس کی جمع شدائداوراشدّاءآتی ہے (اقرب) تفسیر.مختلف معانی کے لحاظ سے اس کے معنے ایک تو یہ ہوں گے کہ (۱)اوپر جس انسان کا ذکر ہوا ہے وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے یعنی اس کی محبت مال سے بہت بڑھی ہوئی ہے (۲)دوسرے معنے یہ بھی ہو سکتے ہیںکہ یہ آدمی مال کی محبت میں بڑا شجاع ہے یعنی قومی روح اور قومی قربانی اس میں نہیں پائی جاتی یا دینی قربانی اس میں نہیں پائی جاتی اگر خدا تعالیٰ کے لئے کسی قربانی کی ضرورت ہو تو وہ کوئی قربانی نہیں کر سکتا.اگر قوم کی ترقی کے لئے کسی قربانی کی ضرورت ہو تو وہ اس قربانی کو ادا کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا.لیکن اگر کہیں سے مال ملتا ہو تو پھر یہ بڑا دلیر ہو جاتا ہے.یا اس کا مال چھنتا ہو تو خوب مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے.دین کی ہتک ہو جائے،قوم کی ہتک ہوجائے،قوم کی عزت پر حملہ ہو جائے، قوم کی آزادی اور حریت پر حملہ ہو جائے اس کی غیرت جوش میں نہیں آتی وہ بزدل بن کر اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کے مال پر ہاتھ ڈال دے تو پھر جان دینے کے لئے تیار ہوجاتا ہے(۳) تیسرے معنے اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ کے یہ ہو ں گے کہ بِسَبَبِ حُبِّ الْـخَیْـرِ یعنی بخل کی کئی وجوہ ہوتی ہیں.بخل کے معنے ہوتے ہیں روپیہ روک لینا.لیکن یہ ہر شخص جانتا ہے کہ روپیہ روک لینے کی کئی وجوہ ہو سکتی ہیںضروری نہیں کہ ہر شخص ایک وجہ سے ہی بخل کا ارتکاب کرتا ہو.ان وجوہ میں سے جو مال کو روک لینے کے محرک بن جاتے ہیں.کبھی بخل ناداری کی وجہ سے ہوتا ہے مثلاً ایک غریب شخص ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کھانے کے لئے صرف ایک روٹی پڑی ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر یہ ایک روٹی بھی خرچ ہو گئی تو جب بچے جاگیں گے ان کے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا اس لئے وہ روٹی کو سنبھال کر رکھ لیتا ہے ایسی حالت میں ایک فقیر
Page 150
اس کے دروازہ پر آتا اور خیرات مانگتا ہے مگر وہ اسے روٹی نہیں دیتا.اب اس نے بخل تو کیا ہے مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس کافی مال نہیں تھا صرف حسب کفایت تھا یا حسب کفایت سے بھی کم تھا اس وجہ سے وہ اپنا مال دوسرے کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوا.پس کبھی بخل ناداری کی وجہ سے ہوتا ہے نادار انسان بے شک اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے مگر اس لئے کہ اس کے پاس صرف حسب کفایت ہوتا ہے اس سے زائد نہیں.کبھی بخل یعنی مال کو روک لینا اس لئے ہوا کرتا ہے کہ جس مقصد کے لئے روپیہ خرچ کرنا ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک اچھا نہیں ہوتا اگر ایسے مقصد کے لئے جس کو یہ اچھا نہیں سمجھتا کوئی دوسرا شخص لاکھ بار کہے کہ روپیہ خرچ کرو تو وہ کبھی خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا.لوگ اسے بے شک طعنہ دیں اسے بخیل اور کنجوس قرار دیں وہ کہے گا تم مجھے بخیل کہو یا کچھ، میں روپیہ نہیں دوں گا کیونکہ میرے نزدیک جس مقصد کے لئے روپیہ مانگا جاتا ہے وہ پسندیدہ نہیں.لیکن فرماتا ہے یہ شخص ایسا ہے کہ غریب بھی نہیں.پیسے اس کے پاس ہیں ضرورت سے زائد ہیں اور پھر جو مقصد ہے وہ بھی برا نہیں.کہا جاتا ہے کہ قوم کے غریبوں کا خیال رکھو.قوم کے مساکین کا خیال رکھو.قوم کے یتامیٰ کا خیال رکھو.یہ کوئی برا مقصد نہیں کہ اس کے لئے روپیہ خرچ کرنے سے انسان کو ہچکچاہٹ ہو.اگر کہا جاتا کہ اپنے روپیہ سے کنچنیاں نچوائو یا آتش بازی پر اپنا روپیہ صرف کرو تو وہ شخص کہہ سکتا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا میرے نزدیک روپیہ کا یہ مصرف درست نہیں.میں اس بارے میں تمہارے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا.لیکن یہ شخص نہ تو غریب ہے اور نہ مقصد برا ہے بلکہ اس کے بخیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت جو فی ذاتہٖ ایک بے مقصد و بے مدعا شے ہے اسے مال خرچ کرنے سے روکتی ہے.یہ امر ظاہر ہے کہ مال کی محبت فی ذاتہٖ مقصود نہیں ہوتی بلکہ مال ذریعہ ہوتا ہے کچھ اور کام کرنے کا مگر یہ بے مقصد و بے مدعا شے جو مال کی محبت ہے اس کے پیچھے روپیہ صرف کرنے سے رکتا ہے اور اتنا احمق ہے کہ یہ اس چیز کو جو ذریعہ ہے مقصود بنا لیتا ہے اور جس مقصد کے حصول کا وہ ذریعہ ہے اسے بھلا دیتا ہے اس سے بڑھ کر حماقت بھلا کیا ہوگی کہ مال جو حوائج کے پورا کرنے کے لئے ذریعہ ہوتا ہے فی ذاتہٖ مقصود نہیں ہوتا اس کو مقصود بنا لیا جائے اور جس غرض کے لئے روپیہ ہوتا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کسی کے پاس کپڑا تو ہو مگر وہ پھر بھی ننگا پھرے اور جب پوچھا جائے کہ تم کپڑا کیوں نہیں پہنتے تو جواب دے کہ اگر میں نے کپڑا پہنا تو پھٹ جائے گا.ایسا شخص اگر احمق نہیں کہلائے گا تو کیا کہلائے گا.مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے بعض لوگوں کی بھی یہی حالت ہے چنانچہ صبح کے وقت کسی گائوں کی طرف سیر کے لئے نکلو تو تمہیں نظر آئے گا کہ زمیندار ننگے پائوں روڑوں اور کانٹوں پر چلتا چلا جارہا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں جوتی اٹھا ئی ہوئی ہے یا سوٹی سے لٹکا کر اس سوٹی
Page 151
کو اپنے کندھوں پر رکھا ہوا ہے.حالانکہ جوتی تو اس لئے ہوتی ہے کہ کانٹوں اور جھاڑیوں اور کنکروں سے بچائے نہ اس لئے کہ جوتی کو اٹھا لیا جائے اورننگے پائوں کانٹوں اور کنکروں پر چلنا شروع کر دیا جا ئے.مگر زمیندار بچارہ تو غربت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے جانتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوتی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اسے سنبھال کر رکھوںاگر جوتی پھٹ گئی اور مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانا پڑا تو لوگ اسے کیا کہیں گے کہ تیرا باپ ننگے پائوں آگیاہے اور اس کے پاس جوتی کے لئے بھی پیسے نہیں.اسی وجہ سے وہ اپنی جوتی سنبھال کر رکھتا ہے اور اس کی حالت کو دیکھ کر اس کی غربت پر بھی رحم آتا ہے اور اپنے ملک کی حالت پر بھی افسوس آتا ہے.مگر وجہ کچھ ہو بہرحال نظارہ یہی ہوتا ہے کہ جو ذریعہ ہے اس کو مقصود بنالیا جاتا ہے اور جس مقصد کے حصول کا وہ ذریعہ ہوتا ہے اسے بھلا دیا جاتا ہے.جوتی اس لئے ہوتی ہے کہ پائوں کو زخم سے بچائے مگر زمیندار اپنے پیر کو زخمی ہونے دیتا ہے اور جوتی کو بچاتاہے.اسی طرح روپیہ بھی اسی لئے آتا ہے کہ انسان اس کو خرچ کر کے فائدہ اٹھائے.خواہ قومی مفاد پر اس کو خرچ کرے خواہ ذاتی مفاد پر.مگر وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا حالانکہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی رضا اور اس کے دین کی مدد کے لئے روپیہ خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ قومی مفاد کے لئے ہی روپیہ خرچ کرتا یا ذاتی فائدہ کے لئے روپیہ صرف کر دیتا.آخر کسی نہ کسی کام پر تو اسے بہر حال روپیہ صرف کرنا چاہیے تھا.خدا کے لئے نہ سہی قوم کے لئے ہی کارخانے جاری کردیتا تاکہ لوگوں کو مزدوری مل جاتی یا انہیں سستا کپڑا ملناشروع ہو جاتا.یا مثلاً آٹے کی مشین لگا دیتا یا غرباء اور یتامیٰ ومساکین کی ترقی کے لئے کسی صنعت وحرفت یا تجارت کی داغ بیل ڈال دیتا یا مدرسے کھول دیتا تاکہ بچے علم حاصل کریں اور قوم کو عروج حاصل ہو.غرض سینکڑوں طریق ایسے تھے جن سے کام لے کر وہ اپنے روپیہ کو ایسے رنگ میں خرچ کر سکتا تھا کہ اس کی ذات کو بھی فائدہ پہنچتا اور اس کی قوم کو بھی فائدہ پہنچتا.مگر وہ روپیہ کو غلق میں بند کر کے رکھ لیتا ہے نہ خدا کے لئے خرچ کرتا ہے نہ قومی مفاد کے لئے خرچ کرنے پر تیار ہوتا ہے اور آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی دولت بڑھتی نہیں بلکہ سمٹ کر محدود ہو جاتی ہے.کسی صوفی کا قول ہے کہ تو روپیہ دے تاکہ وہ تیری طرف واپس لوٹے تو روپیہ کو روک کر نہ رکھ کہ وہ تیرے لئے عار بن جائے.دنیا میں جتنی قومیں روپیہ خرچ کرتی ہیں ان کا مال بڑھتا ہے مگر جو روپیہ کو روک کر رکھ لیتی ہیں ان کی دولت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے.پس فرماتا ہے اگر ان لوگوں کو خدا بھول گیا تھا اور وہ اس کی رضا کے لئے روپیہ خرچ کرنا ایک بے معنی بات سمجھتے تھے تو کم ازکم انہیں اتنا تو چاہیے تھا کہ قوم کے لئے روپیہ خرچ کرتے مگر ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جن چیزوں کے لئے روپیہ رکھا جاتا ہے جن چیزوں کے لئے روپیہ کو تلاش کیا جاتا ہے جن چیزوں کے لئے روپیہ کو حاصل کیا جاتا
Page 152
ہے ان چیزوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس روپیہ رہ جائے جو فی ذاتہٖ مقصود نہیں ہوتا بلکہ کسی اور چیز کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے.وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا کا مطلب صوفیاء کے نزدیک اوپر کی آیات کا صوفیاء نے اپنے رنگ میں ایک اور مطلب بیان کیا ہے.وہ کہتے ہیں عَادِیَات سے مراد سالکوں کے نفوس ہیںاورمراد یہ ہے کہ وہ کمالات روحانیہ کے حصول کے لئے بے تاب ہو کر دوڑتے اور جدو جہد کرتے ہیںحتی کہ ان کا سانس پھول جاتاہے اور لفظ عَادِیَات میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خیرات اور نیکیوں کے حصول کے لئے صبح شام کام میں لگے رہتے ہیں ایک کام کر کے بس نہیں کر دیتے بلکہ اس کے بعد دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں.دوسرا کام ختم ہوتا ہے تو تیسرا کام شروع کردیتے ہیں.تیسرا کام ختم ہوتا ہے تو چوتھا کام شروع کر دیتے ہیں.غرض ایک دوڑ ہے جس میں مشغول ہوتے ہیں.ابھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر کسی غریب کی خدمت گذاری میں مصروف ہو جاتے ہیں.اس سے فارغ ہوتے ہیں تو تعلیم کا کام شروع کر دیتے ہیں وہ کام ختم ہوتا ہے تو کسی اور نیکی کو سر انجام دینے لگ جاتے ہیں.غرض یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دوڑ دوڑ رہے ہیںاور چاہتے ہیںکہ اس میدان میں دوسروں سے سبقت لے جائیں.پس وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا سے مراد یہ ہے کہ سالک خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لئے ہر رنگ اور ہر طریق کو اختیار کرتے ہیںاور یکے بعد دیگرے نیکی کے کام کرتے چلے جاتے ہیں.فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نہ صرف عمل کے ذریعہ بے انتہا تیزی دکھاتے ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کام شروع کر دیتے ہیں بلکہ ان کا دماغ بھی خالی نہیں رہتا وہ اپنے افکار کو ملاءِ اعلیٰ کی دہلیز پر مارتے ہیں یعنی غوروفکر اور تدبر اور سوچ بچار ان کا طرۂ امتیاز ہو تا ہے وہ ایک طرف خدا تعالیٰ کے کلام کے معانی معلوم کرتے ہیں تو دوسری طرف قانون قدرت پر گہری نظر ڈال کر اس کی حکمتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں.غرض اپنے افکار کو وہ شریعت اور قانون قدرت دونوں پر مارتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں انوار ومعارف پیدا ہونے لگتے ہیں جیسے چقماق پر ضرب لگا نے سے آگ پیدا ہوتی ہے اسی طرح وہ اپنے افکار کے ذریعہ جب ایک طرف شریعت پر اور دوسری طرف قانون قدرت پر ضربیں لگاتے ہیں تو ایک نور ظاہر ہوتا ہے اور اس نور سے صبح پیدا ہوجاتی ہے جس کا فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا میں ذکر آتا ہے جب ان کی کوششوں اور جدو جہد کے نتیجہ میں صبح پیدا ہوتی ہے جس سے مراد انوار سماویہ کا ظہور ہے تو جیسے صبح کے وقت بیسیوں چیزیںجو رات کو نظر نہیں آتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں.اسی طرح ان کو اپنے اور اپنی قوم کے وہ عیوب نظر آنے لگ جاتے ہیں جو انوار سماویہ کے ظہور سے پہلے مخفی ہوتے ہیں.انسان
Page 153
کے چہرے پر میل ہوتی ہے.ادھر ادھر چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں مگر اسے رات کی تاریکی کی وجہ سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی ذات میں یا اس کے گردوپیش کے لوگوں میں کیا کیا نقائص ہیں جب صبح ہوتی ہے تو اسے فوراً نظر آجاتا ہے کہ فلاں چیز سیاہ ہے اور فلاں سفید.فلاں اچھی ہے اور فلاں بری.اسی طرح جب سالک اس مقام پر پہنچتے ہیں تو انوار سماویہ کے ظہور سے جو صبح پیدا ہوتی ہے اس کی روشنی میں انہیں اپنی وہ باریک کمزوریاں بھی معلوم ہو جاتی ہیں جو ان انوار کے ظہور سے پہلے مخفی ہوتی ہیں اور انہیں اپنی قوم کے وہ عیوب بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیںجو پہلے نظر نہیں آیا کرتے تھے گویا علم کامل نہ ہونے کی وجہ سے جو عیوب پہلے مخفی ہوتے ہیں وہ اس صبح کے نتیجہ میں ظاہر ہو جاتے ہیں اپنے نفس کے بھی اور اپنی قوم کے بھی.جب انہیں اپنے اور اپنی قوم کے عیوب نظر آتے ہیں تو فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا وہ اس کی وجہ سے مُغِیْـر بن جاتے ہیں یعنی اپنے عیوب پر بھی حملہ کر دیتے ہیںاور اپنی قوم کے عیوب پر بھی حملہ کر دیتے ہیں.اپنی صفائی میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنی قوم کی صفائی میں بھی مشغول ہوجاتے ہیں.فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا پھر اس حالت ظہور انوار میں وہ اپنی آوازوں کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جاتے ہیں یعنی جب وہ عادات اور ہوا و ہوس پر حملہ کرتے ہیں.جب وہ اپنے عیوب پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنی قوم کی اصلاح کے لئے اس کے عیوب کو مٹانے کے لئے بھی کمر بستہ وتیار ہو جاتے ہیں تو اس وقت جانتے ہیں کہ ہمیں محض اپنی کوششوں اور تدابیر سے کامیابی نہیں ہوسکتی ہم جتنا زور لگائیں گے وہ بہر حال ناقص ہو گا اور پھر بھی کچھ کمزوریاں ہماری ذات میں باقی رہ جائیں گی اور ہماری قوم میں بھی باقی رہ جائیں گی ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اپنی کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ اس اہم کام میں ہماری مدد فرمائے اور اپنے فضل سے ہماری ناچیز مساعی میں برکت ڈالے چنانچہ وہ خدا تعالیٰ کے دربار میں اپنی آوازیں بلند کرنی شروع کر دیتے ہیں.آہ وزاری اور چیخ وپکار سے کام لیتے ہیں.درد مندانہ دعائوں سے اس کے فضل کو جذب کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا تو آ اور ہماری مدد کر اور ہمارے دشمن کو تباہ وبرباد کر.جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں یعنی ایک طرف وہ اپنے عیبوں اور اپنی قوم کے عیبوں کو دور کرنے کے لئے ذاتی طور پر کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کے دربار میں چیخ وپکا ر شروع کر دیتے اور اس سے دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ان کی مددکرے اور اس دشمن کو تباہ کرے جو انہیں خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کے راستوں سے دور پھینکنا چاہتا ہے تو وہ کامیاب ہوجاتے ہیں اور وہ اس پہلی جماعت میں مل جاتے ہیں جو ان سے پہلے اعلٰی عِلِّیِّیْن
Page 154
میں شامل ہو چکی ہے یہ معنے فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا کے ہیں یعنی وہ جَمْعًا جو حقیقت میں جماعت کہلانے کی مستحق ہے اس میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس صورت میں یہاں جَمْعًا کی تنوین عظیم الشان کے معنوں میں سمجھی جائے گی اور آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ پھر وہ جماعت جو ایک ہی جماعت کہلانے کی مستحق ہے یعنی اعلٰی عِلِّیِّیْن والی جماعت اس میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں جس کے لئے انہیں دنیا میں پیدا کیا گیا تھا.یہ نکتہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ سالک ایک طرف تو اپنی کوششوں سے کام لیتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ شیطان کے مقابلہ میں ان کی مدد کرے اس کے متعلق ایک صوفی کا بھی لطیف واقعہ بیان کیا جاتا ہے.لکھا ہے کہ ان کے پاس کوئی شاگرد تصوّف کے مسائل سیکھنے اور ان کی صحبت سے مستفیض ہونے کے لئے آیا اور کچھ مدت تک اپنی روح کی صفائی کے لئے ان کی خدمت میں حاضر رہا.کچھ عرصہ کے بعد علم تصوّف سیکھ کر اس نے چاہا کہ میں اب واپس جائوں اور اپنی قوم کی درستی کروں.جب وہ چلنے لگا تو اس نے کہا حضور مجھے کوئی آخری نصیحت کردیں.انہوں نے کہا تم مجھے یہ بات بتائو کہ کیا تمہارے ملک میں بھی شیطان ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوا کہ مجھ سے یہ کیا سوال کیا گیا ہے کہنے لگا حضور کیا شیطان کسی خاص جگہ کی چیز ہے وہ تو ہر جگہ ہوتاہے.انہوں نے فرمایا اچھا اگر کبھی شیطان نے تمہیں پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستہ میں اس نے تمہیں بڑھنے نہ دیا تو تم کیا کروگے.علم تو سیکھ گئے ہو لیکن تم جانتے ہو کہ شیطان بھی ہر وقت گھات میں لگا رہتا ہے اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لئے اپنا پورا زور صرف کر دیا کرتا ہے.جب تم نے عبادتیں شروع کیںاور کوشش کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی مقام حاصل ہو جائے اور ادھر شیطان نے تمہاری ایڑی پکڑ لی اور وہ تمہیں ورغلانے لگا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا حضور میں شیطان کا پورا مقابلہ کروں گا.انہوں نے کہا بہت اچھا.مان لیا کہ تم نے شیطان کا مقابلہ کیا.شیطان کو شکست ہو گئی اور تم جیت گئے.لیکن جب پھر تم آگے بڑھنے لگے اور شیطان نے تمہیں پھر آپکڑا تو تم کیا کرو گے.آخر شیطان مرتا تو نہیں کہ انسان یہ سمجھ لے کہ میں اسے مار کر امن میں آجائوں گا.تم زیادہ سے زیادہ اس کے حملہ سے وقتی طور پر محفوظ ہو سکتے ہو لیکن اس خطرہ سے آزاد نہیں ہو سکتے کہ ممکن ہے وہ تم پر دوبارہ حملہ کر دے.دوبارہ ہٹایا تو تیسری بار حملہ کر دے.پس میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ تم شیطان کا مقابلہ کروگے اور پھر اس سے اپنا پیچھا بھی چھڑا لو گے لیکن اگر اس نے ہزار مقابلہ کے بعد بھی تمہیں آپکڑا تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں پھر مقابلہ کروں گا.وہ بزرگ فرمانے لگے میں مان لیتا ہوں کہ اب کی د فعہ بھی تم کامیاب ہو جاتے ہو اور شیطان کو تم بھگا دیتے ہو لیکن تم پھر اپنے کام میں مشغول ہوتے ہو تو شیطان آجاتا ہے ایسی حالت میں تم اس کا کیا علاج کرو گے؟ وہ حیران
Page 155
ہو کر کہنے لگا کہ پھر مقابلہ کروں گا.استاد نے کہا اگر ساری عمر تم نے شیطا ن کے مقابلہ میں ہی گذار دی تو خدا تعالیٰ کے پاس کب پہنچو گے.اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا اب مجھے ایک اور بات بتائو.اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے کے لئے جائو اور اس کے صحن میں کتا ہو.تم اندر داخل ہونے لگو تو وہ تمہاری ایڑی پکڑ لے تو اس وقت تم کیا کرو گے ؟اس نے کہا اگر میرے پاس ڈنڈا ہو گا تو میں اسے ڈنڈا ماروں گا پتھر پڑا ہو گا تو میں پتھراٹھا کر ماروں گا.کہنے لگے بہت اچھا تم نے اسے مارا اور وہ علیحدہ ہو گیا.لیکن جب پھر تم دوست کے دروازہ کی طرف بڑھنے لگے اور اس نے تمہیں پکڑ لیا تو تم کیا کرو گے.کتا تو مکان کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مکان کے اندر داخل ہونے دے؟ کہنے لگا میں پھر اس کا مقابلہ کروں گا اوراسے ہٹائوں گا.انہوں نے فرمایا مان لیا کہ اب کی مرتبہ بھی وہ ہٹ گیا اور تم کامیاب ہو گئے لیکن اگر تیسری بار تم پھر بڑھنے لگے اور اس نے پھر تمہیں آپکڑا تو تم کیا کروگے ؟وہ کہنے لگا میں گھر والے کو آواز دوں گا کہ ذرا باہر نکلنا تمہارا کتا مجھے اندر آنے نہیں دیتا اسے روکوکہ میں اندر داخل ہو سکوں.وہ بزرگ فرمانے لگے شیطان کا بھی یہی علاج ہے.شیطان اللہ میاں کا کتا ہے جب وہ تمہاری ایڑی آپکڑے اور تمہیںاللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے نہ دے تو اللہ میاں کو ہی آواز دینا کہ شیطان مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دیتا اسے روک لیں.یہی طریق ہے جس سے شیطان تم پر حملہ کرنے سے رک سکتا ہے ورنہ تمہارے ہٹانے سے کیا بنتا ہے.تم دس بار بھی ہٹائو گے تو وہ دس بار تم پر لوٹ لوٹ کر حملہ کرتا رہے گا.اسی کی طرف فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا میں اشارہ کیا گیا ہے کہ سالک ادھر شیطان کا مقابلہ شروع کر تے ہیں.اغارتیں کرتے ہیں.تدابیر اور جدوجہد سے کام لیتے ہیں اور ادھر دعائیں شروع کر دیتے ہیں کہ خدایا ہم مر گئے آ اور ہماری مدد فرما! جب یہ دونوں باتیں ملتی ہیں تب اللہ تعالیٰ کی ملاقات میسر آتی ہے.جیسے اس بزرگ نے کہا کہ دوست سے ملنا چاہتے ہو تو اس کا طریق یہ ہے کہ اپنے دوست سے کہو کہ وہ کتا پکڑ لے.اسی طرح اگر تم ایک طرف کوشش اور جدوجہد سے کام لو گے اور دوسری طرف خدا تعالیٰ سے انتہائی تضرّع اور عجز ونیاز کے ساتھ دعائیں مانگتے رہوگے تب دعوت شاہی پر جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں ان میں تم بھی شامل ہو جائو گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث قرار پائو گے.صوفیاء کے نزدیک فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا سے دلی فریاد والتجا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.چنانچہ حل لغات میں بتایا جا چکاہے کہ نَقْعٌ کے معنے آواز کے بھی ہوتے ہیں.
Page 156
اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِۙ۰۰۱۰ کیا وہ نہیں جانتا کہ جب وہ (لوگ) جو قبروں میں ہیں اٹھائے جاہیں گے.حلّ لُغات.بَعْثَـرَ.بَعْثَـرَ کے معنے ہوتے ہیں نَظَرَ وَفَتَّشَ.کسی بات میں غور وفکر کیا یا کسی پوشیدہ بات کی تفتیش کی.اور بَعْثَـرَ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں فَرَّقَہٗ،بَدَّدَہٗ پراگندہ کر دیا.اِسْتَخْرَجَہٗ فَکَشَفَہٗ وَاَثَارَ مَا فِیْہِ.کسی پوشیدہ چیز کو نکالا اس کو ظاہر کر دیا اور اس کی حقیقت کا اظہار کر دیا.قَلَّبَ بَعْضَہٗ عَلٰی بَعْضٍ یا نیچے کی چیز کو اوپر کر دیا (اقرب) بُعْثِرَ مجہول کا صیغہ ہے اس کے معنے ہوں گے (۱)پراگندہ کر دیا گیا (۲) الٹایا گیا (۳) کسی پوشیدہ چیز کو ظاہر کیا گیا.تفسیر.اَفَلَا يَعْلَمُ ابتدائی ہمزہ استفہام انکاری کا ہے اور چونکہ استفہام کے بعد لَا آیا ہے جو دوسری نفی ہے اس لئے اس کے معنے مثبت کے بن جائیں گے اور اَفَلَا يَعْلَمُ کے معنے ہوں گے ’’کیا وہ نہیں جانتا ‘‘ اب ظاہر ہے کہ اس فقرہ میں کیا بھی انکار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور لَا کے تو معنے ہی انکار کے ہوتے ہیں پس بوجہ د۲و انکار جمع ہو جانے کے ایک استفہام انکاری اور ایک لَا اس کے معنے مثبت کے ہو گئے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہی ہو کہ میں خبیر ہوں اس لئے سنبھل کر چلو.استفہام بہت سے امور کے لئے ہوتا ہے اس جگہ تہدید ووعید کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ ہم خبیر ہیں یعنی اسے عقل سے کام لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ان باتوں سے باز نہیں آئے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا.ہماری زبان میں بھی یعنی پنجابی اور اردو دونوں میں یہ محاورہ استعمال ہو تا ہے کہ’’تم جانتے ہی نہیں میں کون ہوں‘‘ اس کے یہ معنے نہیں ہوتے کہ تمہیں معلوم نہیں بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ تم جانتے ہی ہو کہ مجھے سزا دینے کی طاقت حاصل ہے اور جب تم اس بات سے بخوبی آگاہ ہو تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے.میں تمہیں ہوشیار کر دیتا ہوں کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو گا.اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہاری خوب خبر لوں گا.یہاں بھی استفہام تہدیدو وعید کے لئے آیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ خدا تعالیٰ خبیر ہے یعنی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں پھر جانتے بوجھتے ہوئے وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے.ہم اس فقرہ سے انہیں پھر ہوشیار کر دیتے ہیں کہ سنبھل کر چلو.ایسی ہستی کا جوعلیم وخبیر ہو مقابلہ اچھا نہیں ہوتا.کیونکہ واقف ہستی سے جہاں نیک اعمال والا نڈر ہوتا ہے بد اعمال زیادہ ڈرتا ہے.اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ میں مَا سے مراد انسانوں کی صفات اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ میں مَا
Page 157
استعمال ہوا ہے حالانکہ یہاں انسانوں کا ذکر ہے اور انہی کا انجام اس میں بیان کیا گیا ہے.میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض دفعہ جب کسی صفت کو بیان کرنا مدّ ِنظر ہو تا ہے تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے بھی مَا آجاتا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ صفت اچھی ہو یا بری.بعض دفعہ اچھی صفت کے لئے مَا استعمال ہو جاتا ہے جیسے حضرت مریم علیہا السلام کے متعلق آتا ہے کہ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ( اٰلِ عـمران:۳۷) اور بعض دفعہ بُری صفت کے لئے مَا استعمال ہو تا ہے جیسے اس جگہ ذوی العقول کے لئے مَا آیا ہے اس لئے کہ ان کی صفتِ تعطل و عدم حرکت کی طرف اشارہ مقصود ہے.درحقیقت دنیا میں انسان وہ کہلاتا ہے جس میں حرکت ہو.جس کے اندر ترقی کی امنگ ہو.جس میں نیک تبدیلی کی خواہش ہو اور جس کے اعمال اس کی زندگی کا ثبوت دے رہے ہوں.اگر کوئی شخص زندگی کی علامات اپنے اندر نہیں رکھتا.اس کی امنگیں مردہ ہو چکی ہوں.اس کی ہمت کوتاہ ہو.اس کے خیالات افسردہ ہوں.اس کے دل کے کسی گوشہ میں بھی اپنی ترقی کا کوئی جذبہ موجود نہ ہو.اس کی قوت عملیہ پر مردنی چھائی ہوئی ہو اور اس کے اعمال سے نحوست ٹپک رہی ہو تو ایسے شخص کو قطعاََ زندہ نہیں کہا جا سکتا.زندہ وہی کہلاتا ہے جس کے اندر زندگی کے آثار پائے جاتے ہوں.اگر کوئی فرد اپنی زندگی کے آثار کو کھو بیٹھتا ہے یا کوئی قوم زندگی کے نشانات اپنے اندر نہیں رکھتی تو وہ ہرگز زندہ نہیں کہلا سکتی.اہل مکہ کو مَا فِي الْقُبُوْرِکہنے کی وجہ اس جگہ مَا فِي الْقُبُوْرِ سے اہل مکہ مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ قوم وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے محروم ہے جو کسی قوم کی زندگی کا نشان ہوا کرتی ہیں.بے شک یہ لوگ بظاہر زندہ اور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر در حقیقت مردہ ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں کوئی امنگ نہیں.ترقی کی کوئی خواہش نہیں.عمل کا کوئی جوش نہیں.علم کے حصول کی کوئی تڑپ نہیں.نیک تغیر پیدا کرنے کا کوئی احساس نہیں.یہ چلتے پھرتے زندہ درحقیقت مردہ ہیںاور مردہ بھی ایسے جو مَا فِي الْقُبُوْرِ ہیں.ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے ایسی چیز کو کوئی دوسرا شخص ہلا بھی سکتا ہے.مثلاً پتھر پڑاہوا ہوتا ہے پتھر ایک بے جان چیزہے مگر چونکہ وہ باہر زمین پرپڑا ہوتا ہے بچے اسے ٹھوکر مارتے ہیں تو وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے لیکن وہ چیز جو قبور میں دبی پڑی ہو اسے کوئی ہلا نہیں سکتا پس مَا فِي الْقُبُوْرِ کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اوّل تو خود ان میں حرکت نہیں اور پھر یہ مٹی کے نیچے دفن ہیں کوئی دوسرا شخص بھی ان کو ہلا نہیں سکتا.یہ ان کی کمال درجہ کی مردنی کا اظہار ہے کہ نہ ان میں خود کوئی حرکت ہے اور نہ کوئی دوسرا انہیں حرکت دے سکتا ہے.کئی چیزیں بے جان ہوتی ہیں لیکن دوسرے لوگ ان سے کام لے لیتے ہیں.مثلاً ڈول جس سے پانی نکالا جاتاہے ایک بے جان چیز ہے مگر جب اسے کنوئیں میں ڈالا
Page 158
جاتا ہے تو وہ ہلتا ہے اور پانی لے کر باہر آجاتا ہے.اسی طرح چرخی خود بے جان چیز ہے مگر جب کوئی دوسرا اسے حرکت دیتا ہے تو وہ فوراً حرکت میں آجاتی ہے.مگر جو چیز قبر میں پڑی ہوئی ہو اس میں نہ خود حرکت ہوتی ہے نہ کوئی دوسرا اس میں حرکت پیدا کر سکتا ہے.پس اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ مکہ کے لوگ وہ ہیں جن میں کسی رنگ میں بھی بیداری نہیں پائی جاتی.نہ ان میں خود بیداری ہے نہ کسی بیدار قوم سے ان کا تعلق ہے.بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم میں خود تو بیداری نہیں ہوتی مگر بیدار قوم سے مل کر اس کی حالت بدل جاتی ہے.مثلاً ہندوستان کو دیکھ لو بظاہر ایک مردہ ملک ہے مگر چونکہ ایک زندہ قوم یعنی انگریزوں سے اس کا تعلق ہے اس لئے وہ جنگ کے موقع پر دس بیس لاکھ فوج ہندوستان سے نکال ہی لیتے ہیں.اسی طرح گو ہندوستان کی ساری دولت انگریز لے گئے مگر پھر بھی ایک زندہ قوم سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کی تجارت کی طرف دنیا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے.اب روپیہ چاہے انگریز لے گئے ہوں لیکن ایک زندہ قوم سے تعلق ہونے کی وجہ سے ملک میں بیداری کے آثار پائے جاتے ہیں.پس زندگی کی د۲و ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو کوئی قوم خود زندہ ہو یا کسی زندہ قوم سے اس کا تعلق ہو.مگر جو قبر میں دبی پڑی ہو اس کی ترقی کی کیا صورت ہوسکتی ہے.قبر میں دبے ہونے کے معنے یہ ہیں کہ مکہ والوں میں نہ آپ زندگی پائی جاتی ہے نہ کسی زندہ قوم سے ان کا تعلق ہے گویا ان میں ذاتی زندگی بھی نہیں اوروہ اضافی زندگی بھی نہیں جو دوسروں سے تعلق رکھ کر پیدا ہوتی ہے.اہل مکہ کی اس انتہا ئی گری ہوئی حالت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ.ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا زمانہ لانے والا ہے جب یہی قوم جو نہ ذاتی زندگی رکھتی ہے نہ کسی طاقتورقوم سے اس کا تعلق ہے اس میں بھی ہم حرکت پیدا کر دیں گے.یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس طرح مقنا طیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے اسی طرح اسلام کی بدولت آخر اہل مکہ میں بھی جو مَا فِي الْقُبُوْرِ تھے ایک حیرت انگیز بیداری پیدا ہو گئی وہ تھے تو مردہ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کی مردہ ہڈیوں میں بھی ایک جان آگئی اور ان میں ایسی حرکت پیدا ہوئی کہ جس کی مثال ان کی زندگی کے دنوں میں دکھائی نہیں دیتی.آخر عرب لوگ ہمیشہ سے مردہ قوم نہیں تھے.ان پر ترقی کا دور بھی آچکا تھا مگر دنیا کی کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ اسلام سے پہلے ان میں زندگی کے وہ آثار پائے جاتے ہوںجو اسلام کے ظہور پر ان میں پیدا ہوئے.اسلام سے پہلے سارے عرب کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ مکہ کے لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کسی قوم پر حملہ کیا ہو.مگر اسلام نے اس مردہ قوم کی ہڈیوں میں بھی ایسا ہیجان پیدا کر دیا
Page 159
اور ایسا جوش اور ولولہ ان کے قلوب میں بھر دیا کہ وہ تین سو میل دو ر اپنے شہر سے نکل کر باہر گئے اور احد میں انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا.حالانکہ مکہ والوں نے کبھی اپنی بڑائی کے زمانہ میں بھی کسی غیر قوم پر حملہ نہیں کیا تھا.جیسے ٹمٹماتا ہوا چراغ جب بجھنے لگتا اور اس کا تیل ختم ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو آخری دفعہ وہ اچھل کر جلتا اور پھر ختم ہو جاتا ہے اسی طرح جب انہیں اسلام کے مقابلہ میں اپنی موت نظر آئی تو ٹمٹماتے چراغ کی طرح انہوں نے بھی آخری سنبھالا لیا اور تین سو میل پر جا کر اسلام سے ٹکر لی.چنانچہ احزاب میں انہوں نے حملہ کیا.احد میں انہوں نے حملہ کیا.بدر اولیٰ میںانہوں نے حملہ کیا اور بدر ثانیہ میں انہوں نے حملہ کیا یہ چار جنگیں ایسی ہیں جن میں مکہ والے تین تین سو میل دور اپنے گھروں سے باہر نکل کر گئے حالانکہ پہلے کسی تاریخ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مکہ کے لوگوں نے اتنی دور جاکر کسی غیر قوم پر حملہ کیا ہو.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ یہ بےشک مردہ ہیں مگر ان مردوں کو بھی ایک دن ہم کھینچ کر باہر لے آئیں گے.جیسے بجلی کی رو کسی دوسری چیز پر ڈالو تو وہ بھی اچھلنے کودنے لگ جاتی ہے اسی طرح مکہ والوں کا حال ہوا.ان کی مردہ ہڈیوں میں بھی جان آگئی.اور گویہ مخالفت کی وجہ سے ہی آئی مگر بہر حال آئی اسلام اور مسلمانوں کے تعلق کی وجہ سے.اس کے بغیر ان میں خود بخود پیدا نہیں ہوگئی.وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِۙ۰۰۱۱ اور جو کچھ سینوں میں (چھپاپڑا)ہے نکال لیا جائے گا.تفسیر.پہلی آیت میں یہ بتا یا گیا تھا کہ مکہ کے لوگ جو آج تمہیں مردہ دکھائی دیتے ہیں ان کی رگوں میں بھی اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جوش میں زندگی کا خون دوڑنے لگے گا اور وہ مسلمانوں کو کچلنے کے لئے بڑھ بڑھ کر حملے شروع کر دیںگے اب اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے کھینچ کر باہر نکال لیا جائے گا یعنی وہ گند اور خبث اور شرارت جو اس قوم کے دل میں نبوت سے دوری اور شرک کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا اور لوگوں کو بتادیا جائے گا کہ اندرونی طور پر یہ کیسے گندے اور ناپاک انسان ہیں.مکہ کے لوگ چونکہ مجاور تھے ان کے کلام میں بڑا تکلف پایا جاتا تھا جو بھی مکہ میں آتا اسے بڑے تپاک سے
Page 160
ملتے اور کہتے آئیے تشریف لائیے.آپ لات کے پاس جائیں گے.عزّیٰ پر چڑھاواچڑھائیں گے.منات کے سامنے ماتھا ٹیکیں گے.جو بھی خدمت ہو ہم اسے بجا لانے کے لئے حاضر ہیں.وہ سمجھتا کہ مکہ والے بڑے مہذب ہیں، بڑے نیک اور دین کے خادم ہیں دیکھو کس محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کیسا اعلیٰ درجہ کا لوگوں سے سلوک کرتے ہیں ذرا بھی ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا.غرض ان کی طبیعتوں میں تو گند بھرا ہوا تھا لیکن بظاہر بڑے مؤدب تھے اور کسی شخص کے وہم وگمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ اخلاق سے عاری ہو چکے ہیں اور دراصل یہی حال ہر منافق اور چالباز انسان کا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر بڑا مؤدب ہوتا ہے مگر اندرونی طور پر اس کی طبیعت میں گند بھرا ہوا ہوتا ہے.لوگ جب حج کے لئے جاتے ہیں تو جہاز سے اترتے ہی انہیں بعض ایسے آدمی مل جاتے ہیں جو بڑی محبت سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے ہم آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تیار ہیں.وہ اردو بھی جانتے ہیں، وہ پنجابی بھی جانتے ہیں، وہ کشمیری بھی جانتے ہیں، وہ پشتو بھی جانتے ہیںاور بعض لوگ تو ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ بڑے اطمینان سے جہاز پر آکر حاجیوں کا اسباب اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور قلیوں سے کہتے ہیں کہ ادھر آئو اور اسباب اٹھائو.جو شخص ان کے ہتھکنڈوں سے واقف ہوتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ لوٹنے کے لئے آئے ہیں مگر جو ناواقف ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ معلوم نہیں یہ لوگ کہاں سے میرے باپ دادا کے واقف نکل آئے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑتا ہے.وہ اسے عزت سے بٹھاتے ہیں ملازموں سے کہتے ہیں کہ ہاتھ دھلائو کھانا لائو، پانی پلائو اور جب وہ کھا کر فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا بل پیش کر دیتے ہیں تب اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو مجھے لوٹ کر لے گئے ہیں.غرض منافق بظاہر بڑا چکنا چپڑاہوتا ہے.دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ بڑا مؤدب ہے حالانکہ اس کے اندرونہ میں کھوٹ بھرا ہوا ہوتا ہے.یہی حال مکہ والوں کا تھا کہ ان کے کلام میں بڑا تکلف پیدا ہو گیا تھا مگر دل گند سے بھرے ہوئے تھے.پس فرماتا ہے ان کی جو چھپی ہوئی بدیاں ہیں ان کو ہم کھینچ کر باہر نکال دیں گے چنانچہ جب اسلام آیا ان کے سارے تکلّفات جاتے رہے اور ان کے وہ گند ظاہر ہوئے کہ الامان.انہوں نے غلاموں پر ظلم کئے.انہوں نے بچوں پر ظلم کئے.انہوں نے عورتوں پر ظلم کئے یہاں تک کہ بعض عورتوں کی شرمگاہوںمیں انہوں نے نیزے مارے اور اس طرح ان کو ہلاک کیا.(الطبقات الکبرٰی لابن سعد زیر لفظ سـمیہ) پھر تشبیب کے ذریعہ اس طرح بہتا ن تراشی سے کام لیا اور ایسی ایسی گندی گالیاں دیںکہ اگر انسان میں شرافت کا ایک شمہ بھی باقی ہو تو وہ ایسی حیا سوز حرکات نہیں کر سکتا.اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نماز کے لئے جاتے ہیں تو سجدہ کی حالت
Page 161
میں کفار آپ کے سر پر اونٹ کی اوجھڑی رکھ دیتے ہیں اور پھر قہقہہ مار کر ہنس پڑتے ہیں گویا انہوں نے بہت بڑا کمال کیا ہے.مکہ والوں کا مجاور ہونا درحقیقت یہ مفہوم رکھتا تھا کہ وہ قوم کے دینی پیشوا اور بزرگ ہیں مگر ان دینی پیشوائوں اور بزرگوںکا یہ حال تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازکے لئے جاتے ہیں خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور وہ لوگ اونٹ کی اوجھڑی جو غلاظت سے لت پت تھی اٹھا کر آپ کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنا اچھا کام کیا.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مکہ والو آج تم بڑے اچھے نظر آرہے ہو اور دنیا تمہارے متعلق سمجھتی ہے کہ تم لات کے پجاری ہو.تم عزّیٰ کے ماننے والے ہو.تم منات کے آگے سر جھکانے والے ہو.تم خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے ہو.تم بڑے بزرگ اور خدا رسیدہ ہو حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارے دل خبث اور شرارت سے بھرے ہوئے ہیںاور ان میں گند ہی گند پایا جاتاہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو کھڑا کر کے تمہارے ایک ایک گند کو ظاہر کر دیں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ تم کیسے ناپاک اور گندے اخلاق کے مالک ہو چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد اہل مکہ کے تکلفات کی چادر سب پارہ پارہ ہو گئی.مسلمانوں کو گالیاںدی گئیں.عورتوں اور غلاموںپر ظلم کئے گئے.صحابہؓ کوگھروںسے نکالا گیا.لڑائیوں میں مارے جانے والوں کے انہوں نے ناک کان کاٹے اور ان کے کلیجے چبائے.پھر احسان فراموشی کا اس رنگ میں مظاہرہ کیا گیا کہ ایک دفعہ کفار میں سے کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور مہمان آئے.مدینہ کی آب وہوا کے ناموافق ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کاخاص طور پر اہتمام کیا اور صحابہؓ سے فرمایا کہ ان کو اونٹنیوںکا دودھ خوب پلائو.چنددنوں کے بعد وہ اچھے ہو گئے تو جاتی دفعہ انہوں نے یہ شرافت کی کہ اونٹوں کے نگران کو مار ڈالا اور اونٹ چرا کر لے گئے(بخاری کتاب الطب باب الدّواء بابوال الابل ) یہ کیسی حد درجہ کی خباثت ہے کہ بیماری میں علاج کرواتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور جب اچھے ہوتے ہیں تو اونٹ چرا کر لے جاتے ہیں.قادیان میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا اور اب بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بعض مخالف آتے ہیں،کھانا کھاتے ہیں،رہائش اختیار کرتے ہیںاور جب جانے لگتے ہیں تو بستر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے احمدیوں کو خوب زک پہنچائی.وہ بھی اونٹوں کا دودھ پیتے رہے علاج کرواتے رہے اور جب اچھے ہو کرجانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے نگران کو قتل کردیا اور اونٹ چرا کر لے گئے.پھر ان کی دھوکا بازی کی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ بعض لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے
Page 162
لگے وعظ ونصیحت کے لئے ہمارے ساتھ کچھ آدمی روانہ فرمائیں ہماری قوم ہدایت کی متلاشی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اسلام کے مبلغین سے اپنی معلومات میں اضافہ کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستّر ۷۰ قاری روانہ کردیئے.جب وہ گائوں کے قریب پہنچے تو سب نے مل کر ان کو قتل کر دیا اور پھر بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے خوب کیا مسلمانوں کے ستّر ۷۰ آدمی ہم نے مار ڈالے.(بخاری کتاب الجھاد والسیر باب العون بالمدد )حالانکہ اس سے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑا.ان کو خدا تعالیٰ نے اور آدمی دے دئیے مگر بے حیائی تو کفار کی ظاہر ہوئی غرض ظلم، فساد، بخل، تکبر، شرارت، احسان فراموشی، دھوکے بازی ،کمینگی، بے حیائی، اتہام تراشی، غلاموں کو ستانا، عورتوں اور بچوں کو دکھ دینا سب عیوب ان میں پائے جاتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ ایسے برے ہیں.اہل عرب سمجھتے تھے مکہ والے کتنے اچھے ہیں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج تم اچھے سمجھے جاتے ہو لیکن یاد رکھو ایک دن ہم تمہارے سب گند ظاہر کر دیں گے.چنانچہ اسلام کے آنے پر مکہ والوں کا گند ایسا ظاہر ہوا کہ مجاورت کا مصنوعی تقویٰ دھجی دھجی ہو گیا اور اسی وقت اس کی اصلاح ہوئی جب وہ اسلام کی غلامی میں آکر داخل ہوئے.اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّخَبِيْرٌؒ۰۰۱۲ اس دن ان کا رب یقیناً ان کی نگرانی کرنے والا ہو گا.تفسیر.لفظ خَبِیْر کا استعمال میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بصیر اور علیم کے الفاظ صرف علمی حالت پر دلالت کرتے ہیں لیکن خَبِیْر کا لفظ اس علم کے مطابق عمل کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی خَبِیْر میں علاوہ خبر رکھنے کے مجرموں کی سزااور ان کی خبر لینے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے.چنانچہ یہ آیت میرے اس دعویٰ کی مصدق ہے يَوْمَىِٕذٍ کا لفظ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ محض علم تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حاصل ہے اس دن عالم ہونے کے کوئی معنے ہی نہیں.پس خَبِیْر میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے ایک یہ کہ اس سے تمہارا کوئی جرم پوشیدہ نہ ہو گا اور دوسرے یہ کہ اس علم تفصیلی کے مطابق وہ اس دن جزا بھی دے گا.يَوْمَىِٕذٍ کے ساتھ قرآن کریم میں صرف خَبِیْر کا استعمال ہوا ہے علیم و بصیرکا استعمال نہیں ہوا.اردو میں بھی ’’ خبر لوں گا‘‘کا محاورہ استعمال ہوتا ہے جو شاید خبیر کے لفظ سے ہی نکلا ہے.اسی طرح پنجابی زبان میں بھی کہتے ہیں ’’میں تیری خبر لانگا‘‘ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں تجھے تیرے اعمال کا بدلہ دوں گا.پس اللہ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّخَبِيْرٌ.اس دن ان کا رب ان کا خبیر ہوگا
Page 163
یعنی نہ صرف ان کے حالات سے واقف ہو گا بلکہ ان حالات کی ان کو جزا بھی دے گا.چنانچہ قرآن کریم میں ہمیشہ يَوْمَىِٕذٍ لَّخَبِيْرٌ ہی استعمال ہوا ہے يَوْمَىِٕذٍ لَّعَلِیْمٌ یا يَوْمَىِٕذٍ لَّبَصِیْرٌ استعمال نہیں ہوا.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں خبیر سے محض علم مراد نہیں بلکہ ان کو سزا دینا مراد ہے اور اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّخَبِيْرٌ کے معنے یہ ہیں کہ اس دن ان کا رب ان کی خوب خبر لے گا.یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم ان کی خبر تو ضرور لیں گے مگر پہلے نہیں بلکہ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ کے بعد.جب تک ان کے چھپے ہوئے گند پوری طرح ظاہر نہیں ہو جائیں گے ہم ان کو سزا نہیں دیں گے.یہ مجرموں کی سزا کے متعلق ایک ایسا اصل ہے جسے بہت سے لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو لوگوں پر مخالفت کے فوراً بعد عذاب کیوں نازل نہیں ہو جاتا.اس شبہ کا اس آیت میں جواب موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو خطاب کرتے ہوئے اس جگہ اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں تو لوگوں کے دلوں میں کئی قسم کے شکوک وشبہات پیدا ہونے لگیں اور وہ یہ خیال کرنے لگ جائیں کہ یہ لوگ تو بڑے بزرگ اور نیک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ہلاک کر دیا.اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کہ کفار مکہ کو قتل کر دو کیونکہ ان کے دل گناہ اور ظلم کے ارادوں سے پُر ہیں تو لوگ کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے.یہ لوگ تو بڑے شریف اور نیکو کار تھے.خدمت دین کے لئے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہو ا تھا ان کو مارنا کس طرح درست ہو سکتا تھا مگر اب جبکہ ان لوگوں کے گند پوری طرح ظاہر ہو چکے ہیں.ان کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے ہر شریف انسان کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں سے مسلمان نہ لڑتے تو کن سے لڑتے.بچوں کو انہوں نے مارا، عورتوں کو انہوں نے مارا، مردوں کو انہوں نے مارا، غلاموں کو انہوں نے مارا اور اس قدر شرمنا ک مظالم ان پر توڑے کہ ان واقعات کو پڑھ کر بے اختیار آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آتے ہیں.اس سے زیادہ بے حیائی اور کیا ہو گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لڑکی کو جن کی شادی بعثت سے پہلے کفار میں ہو چکی تھی محض توحید سے نقار رکھنے کی وجہ سے کفار مکہ نے طلاق دلوادی.ایک دوسری لڑکی کے خاوند سے آپ نے اس کے قید ہونے کے بعد اقرار لیا کہ وہ آپ کی لڑکی کو مدینہ روانہ کر دے گا اس پر جب اس نے ان کو مکہ سے روانہ کیا اور اونٹ پر سوار ہونے پر کسی بدبخت نے ان کے کجاوے کی رسیاںکاٹ ڈالیں اور وہ نیچے گر گئیں وہ اس وقت حاملہ تھیں نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ
Page 164
میں پہنچ کر اسی چوٹ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا.(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام زیر عنوان خروج زینب الی المدینۃ) اب بتائو اس میں کون سی شرافت ہے کہ ایک اکیلی لڑکی اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ جا رہی ہے وہ حاملہ ہے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں رہی مگر کفار شرافت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پر حملہ کرتے ہیں اسے اونٹ سے گرا دیتے ہیں اور اس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اس قسم کے سلوک کو جائز قرار دے سکتا ہے اور کیا کوئی شخص بھی اس قسم کے حالات کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ مکہ والوں میں انسانیت کا کوئی شائبہ بھی پایا جاتا تھا.یہ ایسی ذلیل غیر شریفانہ حرکت تھی کہ ہند جیسی دشمن اسلام عورت نے اس کو سن کر اپنے کفر کی حالت میں بھی اسے برداشت نہ کیا اور جب وہ شخص اس کے سامنے آیا تو اسے طعنہ دیا کہ اب مکہ کے بہادر آدمیوں کا شغل بے کس اور حاملہ عورتوں پر حملہ کرنا رہ گیا مسلمان بہادروں کے سامنے وہ بھیگی بلی کی طرح دبک کر بیٹھ جا تے ہیں.جب مکہ والوں کے مظا لم بڑھ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم مجھے اس شہر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو میں تمہارا شہر ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تم اب تو میرا پیچھا چھوڑ و.مگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے اور تین سو میل پر پہنچ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں.یہ وہ گند ہے جو ان کے دلوں میں مخفی تھا اور جس کے ظہور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا.پس حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ کو پہلے اور اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّخَبِيْرٌ کو بعد میں رکھنا بے معنی نہیں بلکہ اس میںبہت بڑی حکمت ہے اور وہ یہ کہ ہم پہلے ان لوگوں کے گند ظاہر کریں گے اور پھر ان پر مسلمانوں سے حملہ کرائیں گے تا دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ظلم کیا.وہ ان برائیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ہمارے حکم کے ماتحت ان کو ماریں گے اور خوب ماریں گے اور دنیا بھی تسلیم کرے گی کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا درست کیا انہوں نے مارا تو اچھا کیا بلکہ انہیں اور زیادہ مارنا چاہیے تھا کیونکہ وہ اسی بات کے مستحق تھے.پس حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ کو پہلے رکھ کر اس حجت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کفار پر پوری کی جائے گی.فرماتا ہے ہم انہیں پہلے سزا نہیں دیں گے بلکہ حجت تمام ہونے پر سزا دیں گے بے شک پہلے بھی ان کے دلوں میں وہی گند تھا جو بعد میں ظا ہر ہوا مگر پہلے اگر ہم سزا دیتے تو دنیا کہتی یہ تو بڑے بزرگ تھے.نیک اور پارسا تھے ان کو کیوں سزا دی گئی ہے مگر اب لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے.وہ تسلیم کریں گے کہ جو کچھ ان سے سلوک ہوا وہ با لکل بجا اور درست ہے غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَىِٕذٍ لَّخَبِيْرٌ ہم خبیر ہیں ان لوگوں کے اندرونی حالات کو خوب جانتے ہیں مگر ہم حجت تمام ہونے کے بعد ان کو
Page 165
سزا دیں گے.پہلے ان کے گندظاہر کریں گے اور پھر مسلمانوں سے حملہ کرائیں گے بے شک ہم خبیر ہیں اور ہم پہلے بھی ان کے حالات کو جانتے تھے مگر ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے تقدس کا کوئی خیال باقی رہے.ہم اس وقت ان کو سزا دیں گے جب حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ہو جائے گا اور ان کے گند لوگوں پر اچھی طرح ظاہر ہو جائیں گے.
Page 166
سُوْرَۃُ الْقَارِعَۃُ مَکِّیَّۃٌ سورۃ القارعہ یہ مکی سورۃ ہے وَھِیَ اِحْدٰی عَشْـرَۃَ اٰیَۃً دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَفِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے سوا گیارہ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ قارعہ مکی ہے سورۃ القارعہ بالاتفاق مکی سورتوں میں سے ہے.(فتح البیان سورۃ القارعۃ ابتدائیۃ) مستشرقین یورپ بھی اس کے مکی ہونے کے متعلق متفق ہیں.جرمن مستشرق نولڈکے اور سرمیور نے اسے ابتدائی مکی سورتوں میں سے قرار دیا ہے.)A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry Vol:iv P:272( ترتیب سورۃ یہ سورۃ بھی پچھلی ترتیب کے لحاظ سے اس طرح پر آتی ہے کہ سورۃ العادیات میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ترقی اور کامیابی بیان کی گئی تھی جو ابتدائی زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور اب القارعہ میں اس آخری دور کے متعلق آپ کے سلسلہ کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ پھر اسلام کے لئے مصیبت اور تکالیف کے دن ہوں گے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) اَلْقَارِعَةُۙ۰۰۲ مَا الْقَارِعَةُۚ۰۰۳ (دنیاپر) ایک شدید مصیبت (آنے والی ہے) وہ مصیبت کس قدر عظیم ہے.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُؕ۰۰۴ اور (اے مخاطب) تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ (عظیم الشان) مصیبت کیاہے.حلّ لُغات.اَلْقَارِعِۃُ.اَلْقَارِعَۃُ:ـ قَرَعَ سے اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے اور قَرَعَ (یَقْرَعُ قَرْعًا)
Page 167
الْبَابَ کے معنے ہیں دَقَّہٗ دروازہ پر دستک دی اور قَرَعَ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں ضَـرَبَہٗ کسی چیز کو مارا اور قَرَعَ صِفَاتَہٗ کے معنے ہوتے ہیں تَنَقَّصَہٗ وَعَا بَہٗ اس کی صفات کی تنقیص کی اور اس پر عیب لگایا اور قَرَعَ زَیْدًا اَمْرٌکے معنے ہوتے ہیں اَتَاہُ فَـجْأَۃً اچانک کوئی معاملہ اس سے پیش آگیا اور قَرَعَ السَّھْمُ الْقِرْطَاسَ کے معنے ہوتے ہیں اَصَا بَہٗ ہدف پر تیر لگ گیا (اقرب) گذشتہ مفسرین نے قَارِعَۃ کے معنے قیامت کے کئے ہیں اور چونکہ قَرْعٌ کے ایک معنے شدید آواز کے بھی ہیں گو عام لغت کی کتب میں یہ معنے نہیں نکلے مگر تفاسیر میں قَرْعٌ کے معنے شدید آواز کے بھی بتائے گئے ہیں.اس وجہ سے بعض مفسرین نے قَارِعَۃ کے معنے یہ بھی کئے ہیں کہ اس سے مراد اسرافیل کی وہ گرج ہے جو قیامت کے قریب ہوگی اور جس سے سب لوگ مر جائیں گے ( فتح البیان سورۃ القارعۃ ).قَرَعَ کے معنے تو اوپر بیان ہوچکے ہیں.لیکن اَلْقَارِعَۃُـ کی شکل میں اس لفظ کے کچھ الگ معنے بھی ہوتے ہیں.چنانچہ اَلْقَارِعَۃُـ کے ایک معنے قیامت کے بھی کئے گئے ہیں کیونکہ وہ مختلف قسم کے صدمات اور تخویف کے سامان اپنے ساتھ لائے گی.اسی طرح اس کے ایک معنے اَلدَّاہِیَۃُ کے بھی ہیں یعنی اچانک آنے والی کوئی عظیم الشان مصیبت اور اَلْــقَــارِعَــۃُـ کے معنے اَلــنَّــکْــبَــۃُ الْــمُــھْــلِکَــۃُ کے بھی ہیں یعنی ہلاک کردینے والی مصیبت اور اَلْقَارِعَۃُـ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بھی کہتے ہیں جن کو اصطلاحاً سرایا کہا جاتا ہے.عام اصطلاح میں تو سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوں مگر اس کے اصل معنے چھوٹے چھوٹے لشکروں کے ہیں (اقرب).تفسیر.قرآن کریم میں قَارِعَۃ کا لفظ تین موقعوں پر آیا ہے (۱) سورئہ رعد (۲) سورۃ الحاقہ (۳) زیر تفسیر آیت.سورئہ رعد رکوع ۴ میں آتا ہے وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ١ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.(الرّعد:۳۲).یعنی کفار کی حالت برابر اس طرح رہے گی کہ ان کے اعمال کی وجہ سے یعنی ان تکالیف اور تعذیب کے ایک لمبے سلسلہ کی وجہ سے جو مسلمانوں کو مٹانے کے لئے انہوں نے جاری کیا ہوا ہے.یکے بعد دیگرے ان کے اوپر لشکرحملہ آور رہیں گے اوراس طرح ان پر ضرب پر ضرب پڑے گی اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ یا پھر اسلامی لشکر ایک دن ان کے گھروں کے پاس آکر اترے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے گا یعنی کفار کی شکست اور اسلام کی فتح کا دن.پھر فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.
Page 168
اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا.اس جگہ قَارِعَۃ سے مراد وہ لشکر ہیں جو متواتر اِدھر اُدھر دشمنانِ اسلام پر حملہ آور ہوتے رہے.ان لشکروں کے ذکر سے چونکہ یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ شاید اسلام نے جارحانہ حملے کئے ہیں اس لئے جہاں اس آیت میں غزواتِ اسلامیہ کے متعلق مخفی پیشگوئی فرمائی گئی وہاں اس شبہ کا بھی ازالہ کردیا گیا.چنانچہ فرماتا ہے تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا یہ لشکر کشی کفار کے حملوں کا نتیجہ ہوگی مسلمانوں کی طرف سے ابتدا نہ ہوگی.ہاں جب مسلمان جواب دینا شروع کریں گے تو کفار کی شرارت ایسی دب جائے گی کہ وہ روز بروز کمزور ہوتے جائیں گے اور اسلام بڑھتا جائے گا اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا یہاں تک کہ ایک دن اسلامی لشکر مکہ کے پاس جاکر اترے گا اور انہیں فتح حاصل ہوجائے گی.قرآن مجید میں لفظ قارعہ کا استعمال دوسری جگہ سورۃ الحاقہ میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَ عَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ.فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ.وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (الحاقۃ: ۵تا۷) ثمود اور عاد نے قَارِعَۃ کا انکار کیا فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ پس ثمود تو ایک ایسے عذاب سے ہلاک کئے گئے جو انتہا کو پہنچا ہوا تھا.وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ اور عاد پر ایک شدید ہوا چلائی گئی.اس قدر شدید کہ اس سے ہیبت ناک آواز پیدا ہوتی تھی.اس ہوا نے ان کو ہلاک کردیا.یہاں دو الگ الگ قسم کے عذاب بیان کئے گئے ہیں اور دونوں کا نام قَارِعَۃ رکھا گیا ہے.جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ قَارِعَۃ کا لفظ اَلدَّاہِیَۃُ اور اَلــنَّــکْــبَــۃُ الْــمُــھْــلِکَــۃُ کے معنوں میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ ثمود اور عاد دونوں قوموں کے نبیوں نے لوگوں سے کہا کہ تم ہمارا انکارنہ کرو.اگر تم انکارکرو گے تو مصائب میں مبتلا ہوجائو گے.مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور انبیاء کی باتیں ماننے سے انکار کردیا.اس پر ان نبیوں نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا اور تم تباہ کردیئے جائو گے.بجائے اس کے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے اور اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے وہ اور بھی ہنسی مذاق کرنے لگے.آخر ثمود پر تو اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ عظیمہ بھیجا جس سے وہ تباہ ہوگئے اور عاد پر ایک شدید ہوا چلائی گئی جس نے ان کو تباہ کردیا.چنانچہ اب تک آثار قدیمہ والے جب ان علاقوں کی زمینیں کھودتے ہیں تو ریت کے تودوں کے نیچے سے بڑے بڑے شہر نکل آتے ہیں.آیت زیر تفسیر میں بھی قَارِعَـۃـ کا لفظ اَلنَّکْبَۃُ الْمُـھْــلِکَــۃُ کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے یعنی ایسی مصیبت جو ہلاک کردینے والی ہو.
Page 169
اَلْقَارِعَۃ وہ عذاب ہے جو کسی نبی کی صداقت کے لئے آئے اوپر کی تمام آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اَلْقَارِعَۃُـ وہ عذاب ہے جو کسی نبی کی صداقت کے اظہار کے لئے آئے خواہ وہ اس کے یا اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہو.جیسے سورئہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَ لَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَۃٌ.یہ قارعہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے اور آپ کے ہی تیار کردہ ہوتے تھے.اور خواہ یہ بلاواسطہ الٰہی فعل سے ظاہر ہو.جیسا کہ سورۃ الحاقہ سے پتہ چلتاہے کہ ثمود پر زلزلہ آیا اور وہ ہلاک ہوگئے.یہ ایک بلاواسطہ الٰہی فعل تھا کسی انسان کا اس میں دخل نہیں تھا یا عاد پر ہوا چلی اور وہ ہلاک ہوگئے.یہ بھی ایک بلاواسطہ الٰہی فعل تھا کیونکہ کوئی انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہوا چلا کر دوسروں کو ہلاک کرسکے.اور خواہ کسی ایسے الٰہی فعل سے ہو جس میں انسانوں کو واسطہ بنا لیا گیا ہو جیسا کہ میرے نزدیک اس سورۃ میں قارعہ سے ایسا عذاب ہی مراد ہے جو ہے تو الٰہی فعل کا نتیجہ مگر اس میں انسانوں کو بھی واسطہ بنالیا گیا ہے.قارعہ ایسے عذابوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ قَرْعٌ کے معنے دستک دینے اور ٹھکرانے کے ہوتے ہیں.جب لوگ خدا تعالیٰ کے مامور کی آواز نہیں سنتے اور روحانی طور پر سوئے رہتے ہیں تو خدا تعالیٰ دستک دے کر جگانے کے لئے کچھ عذاب بھجواتا ہے.ان دستکوں سے آخر وہ روحانی نیند سے بیدار ہوجاتے ہیں اور رسول کی آواز سننے کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں.پس قارعہ وہ عذا ب ہیں جو نبیوں کو منوانے کے لئے دنیا میں آتے ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْقَارِعَةُ دنیا میں ایک قارعہ آنے والی ہے.پھر فرماتا ہے مَا الْقَارِعَةُ یہاں مَا اظہار تفخیم کے لئے آیا ہے اورمراد یہ ہے کہ کیا ہی عظیم الشان وہ قارعہ ہے.جب انسان کسی چیز کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے تو کہتا ہے ’’کیابلا آگئی‘‘ یا ’’کیا مصیبت آگئی‘‘ اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے اس بارہ میں پوچھتا ہے بلکہ اس جملہ سے اس کا مقصود مصیبت کی شدت کا بیان کرناہوتا ہے.اردو میں بھی محاورہ ہے کہ بعض دفعہ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لئے تکرار سے کام لیا جاتا ہے.کہا جاتا ہے.مصیبت.کیا بتائوں کیسی مصیبت.بلا کیا بتائوں کیسی بلا.پس اَلْقَارِعَةُ کے بعد مَا الْقَارِعَةُ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مصیبت جس کا ہم ذکر کررہے ہیں معمولی نہیں بلکہ نہایت عظیم الشان ہوگی.مَا الْقَارِعَةُ میں دوبارہ قارعہ کا لفظ دوہرانے میں ایک حکمت خود قَرْعٌ کا لفظ بھی عظیم الشان آواز اور عظیم الشان تباہی پر دلالت کرتا ہے.لیکن مَا الْقَارِعَةُ نے بتادیا کہ عذاب کی جس قدر شدت قارعہ کے لفظ سے ظاہر ہوتی ہے وہ قارعہ خود اس سے بھی زیادہ شدید عذاب ہے حتی کہ انسان اس پر حیران ہوکر رہ جائے گا.اس جگہ
Page 170
بجائے ضمیر لانے کے اللہ تعالیٰ نے جو اسم کو دہرایا ہے یہ بھی اس عذاب کی عظمت کے اظہار کے لئے ہے مَاالْقَارِعَةُ میں بجائے ضمیر لانے کے اسم کو دہرانے میں حکمت یہ ہے کہ جب ضمیر آئے تو اصل لفظ اوجھل ہوجاتا ہے مثلاً کہتے ہیں جَاءَ زَیْدٌ فَقُلْتُ لَہٗ زید میرے پاس آیا اور میں نے اسے کہا.اب یہ ظاہر ہے کہ زید کا لفظ جتنی حقیقت ظاہر کرتا ہے اتنی حقیقت ضمیر ظاہر نہیں کرتی.یہ کہنا کہ میں نے زید سے کہا اور یہ کہنا کہ میں نے اس سے کہا گو مفہوم کے لحاظ سے کوئی فرق پیدا نہ کرے مگر زید کا لفظ دہرانے سے جو اثر پڑتا ہے وہ محض ضمیر سے نہیں پڑتا.اس جگہ بھی اَلْقَارِعَةُ کے بعد مَا الْقَارِعَةُ میں بجائے ضمیر لانے کے اسم کو دہرادیا گیا ہے.جس سے اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مدّ ِ نظر ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ انسانی نظروں سے غائب ہی نہیں ہوسکتی.ضمیر جب بھی آئے گی غائب کے لئے آئے گی.لیکن وہ مصیبت اتنی بڑی ہوگی کہ انسان یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مَاھِیَ اگر وہ ایسا کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہوگئی.مگر ایسانہیں ہوگا.پس مَا الْقَارِعَةُ نے یہ بتادیا کہ وہ بھولنے والی چیز نہیں، نظروں سے اوجھل ہونے والی چیز نہیں اسی لئے ضمیر کی بجائے اصل لفظ دہرا کر اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم اسے بھولو گے نہیں وہ نہایت عظیم الشان مصیبت ہوگی.الغرض دو چیزوں سے اس قارعہ کی عظمت بیان کی گئی ہے.ایک ’’مَا ‘‘ سے اور ایک ضمیر کی بجائے دوبارہ اسی لفظ کو دہرانے سے.اگر صرف ’’مَا ‘‘ کا لفظ آتا تب بھی اس قارعہ کی عظمت کا ثبوت ہوتا مگر مَا الْقَارِعَةُ سے اس کی دوہری عظمت بیان کردی گئی ہے کہ انسان حیران ہوکر کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا چیز ہے.دوسرے وہ اتنی عظیم الشان چیز ہوگی کہ اس کی ہیبت انسانی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی.جیسے دنیا میں جب کوئی بڑی عظیم الشان مصیبت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہر وقت آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ پھرتا ہے.اسی طرح وہ مصیبت عظمیٰ اتنی شدید ہوگی کہ بھولے گی نہیں.ہر وقت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رہے گی.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ کہہ کر اللہ تعالیٰ پھر تیسری بار اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ اس کی حقیقت کا سمجھنا انسان کے لئے بالکل ناممکن ہے الفاظ میں اس کو ادا ہی نہیں کیا جاسکتا.یہ ویسا ہی بیان ہے جیسے حدیثوں میں جنت کے متعلق آتا ہے کہ لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَـمِعَتْ وَمَا خَطَرَ بِقَلْبِ بَشَـرٍ.(بخاری کتاب التفسیر سورۃ السجدۃ ) نہ آنکھوںنے ایسا دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے واہمہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے.اسی مضمون کی طرف قرآن کریم نے بھی ان الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّاۤ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ (السجدۃ: ۱۸) یعنی جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے کوئی شخص اس
Page 171
اس کے کمال پر دلالت کرتاہے یعنی شدید آواز یا شدید مصیبت.الف لام کبھی کمال کے اظہار کے لئے آتا ہے یعنی یہ بتانے کے لئے کہ اس لفظ سے جو حقیقت ظاہر ہوتی ہے وہ اس مسمّٰی میں بکمال و تمام پائی جاتی ہے.اس جگہ الف لام اسی مضمون کو ادا کرتا ہے اورمراد یہ ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت ہوگی.پھر مَا الْقَارِعَةُ کہہ کر دوسری دفعہ اس کی عظمت کا اظہار کیا اور وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ کہہ کر تیسری دفعہ بتایا کہ ابھی اس کی عظمت کا پورا ذکر نہیں ہوا.درحقیقت وہ اتنی بڑی شے ہے کہ کوئی شخص اس کی حقیقت کو صرف الفاظ سے سمجھ ہی نہیں سکتا اس لئے آج تم اس کی حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے.یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز کی حقیقت کو انسان سمجھ نہیں سکتا یا جس کی عظمت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہوتا ہے جب اس چیز کا ذکر کیا جائے تو لازماً یا تو تمثیل سے کام لینا پڑتا ہے یا پھر اس کے بعض نتائج بیان کردیئے جاتے ہیں.مثلاً کوئی بڑا عمدہ نظارہ ہو اور انسان اس کوایسے قویٰ سے دیکھے جو روحانی ہوں ظاہری قویٰ اس کو نہ دیکھ سکتے ہوں تو دوسروں کے سامنے جب وہ اس نظارہ کا ذکر کرنے لگے گا تمثیلات میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا.لیکن کبھی تمثیلات میں بیان کرنے کی بجائے اس چیز کے اثرات بیان کردیئے جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا.حضرت عائشہؓ نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نُوْرٌ اَنّٰی اَرَاہُ (مسلم کتاب الایمان باب فی قولہٖ علیہ السلام نُوْرٌ اَنّٰی اَرَاہُ) اللہ تعالیٰ تو ایک نور ہے اسے میں کس طرح دیکھ سکتا ہوں.جہاں تک مادی آنکھوں یا جسمانی قویٰ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال ہے یہ ایک یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آسکتا.لیکن دوسری طرف اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ درست ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو نظر بھی آ جاتا ہے.لیکن بہر حال وہ اسی طرح نظر آتا ہے کہ یا تو انسان اس کی صفات سے رویت کرتا ہے اور یا کسی تمثیلی نظارہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو دیکھ لیتا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میںنے خدا تعالیٰ کو ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا ہے (کنز الایمان کتاب الایمان والاسلام الباب الثالث فی لواحق کتاب الایمان ).پس ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ تمثیلی رنگ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صفات الٰہیہ پر غور کرتے ہوئے اس کی رویت کی جائے.جب ہم صفت رب پر غور کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کا وجود ہمارے قریب ہو جاتا ہے.جب ہم صفت رحمانیت پر غور کرتے ہیں تو اس کا وجود ہمارے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے.جب ہم صفت رحیمیت پر غور کرتے ہیں تو وہ ہمارے اور قریب آجاتا ہے.اسی طرح جب ہم اس کی مالکیت پر غور کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ
Page 173
قریب آجاتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعہ انسان کو نظر آجاتا ہے مگر صفات بھی اپنی ذات میں نظر نہیں آتیں بلکہ نتیجہ سے نظر آتی ہیں.جب ہم دنیا میں ربوبیت کے مختلف نظارے دیکھتے ہیں تو ایک رب خدا ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے.جب ہم دنیا میں رحمانیت کے نظارے دیکھتے ہیں تو ایک رحمٰن خدا ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے.جب ہم دنیا میں رحیمیت کے نظارے دیکھتے ہیں تو ایک رحیم خدا ہماری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے.جب ہم دنیا میں اس کی مالکیت کے نظارے دیکھتے ہیں تو مالک یوم الدین خدا کا ایک ناقص تصور ہمارے ذہن میں آجاتا ہے.یہ خدا تعالیٰ کی رویت ہے جو مومنوں کو نصیب ہوتی ہے پھر اس سے اوپر کوئی انسان ترقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انوار اس کے قلب پر نازل ہونے شروع ہوجاتے ہیں اور اس کے اندر نئی طاقتیں، نیا جوش، نئی محبت اور نئی روحانی قوتیں پیدا کر دی جاتی ہیں.پھر اور ترقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طرح درجہ بدرجہ وہ ترقی کرتا چلا جاتا اور ایک رویت سے دوسری رویت کا مقام حاصل کرتا جاتا ہے مگر بہر حال وہ جتنا بھی بڑھ جائے آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اسے حاصل نہیں ہو سکتا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ نُوْرٌ اَنّٰی اَرَاہُ تو اور کون ہے جو کسی روحانی مقام پر پہنچ کر یہ دعویٰ کرسکے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے وہ جو کچھ بھی دیکھے گا خدا تعالیٰ کی ایک تجلی ہوگی جو اس کے اپنے مقام کے مطابق اس پر ظاہر ہوگی.حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ کی یہ تجلی اس رنگ میں ہوئی کہ روح القدس آپ پر کبوتر کی شکل میں نازل ہوا اور اس نے خدا تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچایا(مرقس باب ۱آیت ۱۰).بعض اور انبیاء ایسے ہیںجن پر یہ تجلی کسی اور رنگ میں ہوئی.کسی کو خدا تعالیٰ نار میں نظر آگیا.کسی کو کامل انسان کی صورت میں نظر آگیا.کسی کو صفات الٰہیہ کے ظہور کی صورت میں نظر آگیا اور کسی کے قلب پر اس کا پَرتو پڑ گیا.بہرحال وہ اتنا ہی نظر آئے گا جتنا کسی کا قلب آسمانی انوار سے حصہ رکھتا ہو گا اور تمثیل پر ہی ہر صورت میں کفایت کرنی پڑے گی.غرض ہر ایسی چیز جس کی حقیقت کا سمجھنا انسان کے لئے ناممکن ہو اسے صرف اسی رنگ میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس کے نتائج بیان کر دیئے جائیںیا تمثیلی رنگ میں اس کا نقشہ کھینچ دیا جائے اس لئے پہلے یہ بتا کر کہ اس قارعہ کی حقیقت قبل از وقوع تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی اللہ تعالیٰ اس قارعہ کے نتائج بیان کر کے اسے قریب الفہم بناتا ہے اورفرماتا ہے وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ کون سی چیز تجھے بتا سکتی ہے کہ یہ قارعہ کیا ہے یعنی تمہاری قوت واہمہ ایسی نہیں کہ ہمارے بیان سے تم اس کی حقیقت کو سمجھ سکو اس لئے ہم اس کے کچھ نتائج بیان کر دیتے ہیںتا تم کچھ اس کی عظمت وہیبت کا اندازہ کر سکو.
Page 174
يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِۙ۰۰۵ (یہ مصیبت جب آئے گی)اس وقت لوگ پراگندہ پروانوںکی طرح(حیران پھررہے)ہوں گے حلّ لُغات.فَرَاشٌ.فَرَاشٌ اپنی ذات میں ایک علیحدہ لفظ بھی ہے اور فَرَاشَۃٌ کی جمع بھی ہے فَرَاشَۃٌ کی جمع ہونے کی صورت میں فَرَاشٌ ان پروانوں کو کہا جاتا ہے جورات کو لیمپ کی روشنی میں اکھٹے ہو جاتے ہیں چنانچہ لغت میں لکھا ہے حَیَوَانٌ ذُوْجَنَاحَیْنِ یَطِیْـرُ وَیَتَـھَافَتُ عَلَی ا لسِّـرَاجِ فَیَحْتَـرِقُ.یعنی فراشہ اس کیڑے کو کہا جاتا ہے جو لیمپ روشن ہونے پربے تحاشا اس کی طرف دوڑتا اور جل کر مر جاتا ہے اور فَرَاشٌ کے معنے غَوْغَاءُ الْـجَرَادِ کے بھی ہوتے ہیں (اقرب) یعنی جب ٹڈی دل آتا ہے تو اس سے فضاء میں جوشور کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی فراش کہتے ہیں کیونکہ ٹڈی جب آتی ہے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آتی ہے اور اس کے آنے سے بھنبھناہٹ کی آ واز پیدا ہوتی ہے.بعض مفسرین نے جوائمہ لغت میں سے ہیں انہوں نے فراش کوٹڈی کے معنوں میں بھی لیا ہے.جیسا کہ میں بتا چکا ہوں فَرَاشَۃٌ کی جمع ہونے کے علاوہ فَرَاشٌ اپنی ذات میں ایک علیحدہ لفظ بھی ہے.چنانچہ لغت میں اس کے معنے یہ لکھے ہیں کہ مَا یَبِسَ بَعْدَ الْمَاءِ مِنَ الطِّیْنِ عَلَی الْاَرْضِ آسمان سے پانی برسنے کے کچھ عرصہ بعد زمین پر جو پپڑیاں جم جاتی ہیں ان کو بھی فَرَاشٌ کہتے ہیں (اقرب).اور فَرَاشٌ ان بلبلوں کو بھی کہتے ہیں جونبیذ پرآجاتے ہیں.منقیٰ کوجب پانی میں بھگویا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ بلبلے اٹھنے شروع ہوجاتے ہیں.دراصل جس قدر شکر والی چیزیں ہیں ان کے اندر ایک خاص مادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر ان کوپانی میں بھگویا جائے تو جھاگ وغیرہ پیدا ہونی شروع ہوجاتی ہے.چنانچہ گڑ میں سے، گنے کی رس میں سے، کھجور کی رس میں سے، منقیٰ میں سے کچھ عرصہ کے بعد بلبلے پیدا ہونے شروع ہوجاتے ہیں.جس وقت یہ بلبلے اٹھ اٹھ کر پانی کی سطح پر پھیل جاتے ہیں تو ان کو فراش کہتے ہیں (اقرب).اَلْمَبْثُوْثُ.بَثَّ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور بَثَّ الْـخَیْـرَ (بَثًّا وَبَثَّثَہٗ وَاَبَثَّہٗ) کے معنے ہوتے ہیں نَشَـرَہٗ وَاَذَاعَہٗ.خیر کو پھیلایا (اقرب).یعنی لوگوں میں نیکی پھیلائی یا صدقہ و خیرات کا عام چرچا کیا اور بَثَّ الْغُبَارَ کے معنے ہوتے ہیں ہَیَّجَہٗ غبار کو زمین میں سے اٹھایا (اقرب).جیسے قرآن کریم میں هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا (الواقعۃ:۷) زمین میں سے غبار اٹھانے کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے.وَفِیْ مَعْنٰی نَشْـرِہٖ وَاَذَاعِہٖ ’’ بَثُّو الْـخَیْلَ فِی الْاِغَارَۃِ‘‘.اور یہ جو
Page 175
بَثَّ کا لفظ نَشْـر وَاِذَاعَۃ کے معنوں میں آیا ہے اسی کو وسیع کرکے لغت میں کہتے ہیں بَثُّو الْـخَیْلَ فِی الْاِغَارَۃِ انہوں نے حملہ کیا تو گھوڑے دوڑا کر لے گئے یا بَثَّ کِلَابَہٗ عَلَی الصَّیْدِ شکار کے پیچھے کتے ڈال دیئے.اسی طرح کہتے ہیں خَلَقَ اللہُ الْـخَلْقَ فَبَثَّـھُمْ فِی الْاَرْضِ.اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی اور پھر اسے زمین میں پھیلادیا (اقرب).گویا بَثَّ کے معنے پھیلادینے، دوڑانے یا دور تک لے جانے کے ہوئے.تفسیر.ان تمام معانی کوملحوظ رکھتے ہوئے جو لغت نے بیان کئے ہیں يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ کے ایک معنے تو یہ ہوں گے کہ جیسے پراگندہ پروانے ہوتے ہیں ویسی ہی لوگوں کی کیفیت ہوگی.پروانے کی دو حالتیں ہوتی ہیں.ایک تو وہ جب وہ لیمپ کے سامنے ہو.اور ایک وہ حالت ہوتی ہے جب لیمپ سے علیحدہ ہو.جب روشنی سامنے ہو تو سارے پروانے روشنی کی طرف جاتے ہیں لیکن اگر لیمپ کو اٹھا لو اور اندھیرا کر دو تو کوئی ٹڈا اس کونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کونے کی طرف.سب منتشر اور پراگندہ ہو جاتے ہیںاور اگر برسات کا موسم ہو تو چھوٹے چھوٹے پروانے ہی نہیںبڑے بڑے ٹڈے بھی لیمپ کی طرف جاتے ہیں.اس کی وجہ علم ا لحیوانات کے ماہرین یہ بتا تے ہیں کہ پروانوں کی اصل جگہ زمین کے اندر ہوتی ہے جب بارش برستی ہے تو ان کے دلوں میں امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم باہر نکلیں.چنانچہ باہر نکلنے کی امنگ میں ہی وہ زمین سے باہر آتے ہیں اور جب لیمپ کو جلتا دیکھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی اور سوراخ ہے جس سے پَرے کوئی اور عالم ہے وہ جوش کی حالت میں لیمپ پر کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے لئے آزادی کا مقام باقی ہے.بہرحال کوئی بھی وجہ ہو یہ امر ظاہر ہے کہ جب لیمپ روشن ہو تو پروانے اس کے اردگرد جمع ہوجاتے ہیں اور جب لیمپ بجھادو تو وہ پراگندہ ہوجاتے ہیں.پس يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ کے یہ معنے ہوئے کہ اس وقت لوگ اس حال میں ہوں گے جیسے پراگندہ پروانے ہوتے ہیں جن کو روشنی نظر نہیں آتی اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں گویا لوگوں کی حالت بالکل ایسی ہوگی جیسے بغیر لیمپ کے پروانوں کی حالت ہوتی ہے.انہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی.کوئی جہت ایسی دکھائی نہیں دے گی جو ان کے لئے بچائو کا موجب ہوسکے.وہ حیران ہوں گے کہ ہم کہاں جائیں، کدھرجائیں اور اپنے بچائو کی کیا صورت اختیار کریں.گویا ان کی بے بسی اپنے کمال کوپہنچی ہوگی.چونکہ فَرَاشٌ کے ایک معنے ٹڈیوں کے بھی ہیں اس لئے كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ کے یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ ان کی حالت ان ٹڈیوں کی طرح ہوگی جو پراگندہ کردی جاتی ہیں.اَلْقَارِعَةُ پر بحث کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا
Page 176
کہ ائمہ لغت جو تفسیر کی طرف مائل ہیں ان کے نزدیک قَرْعٌ کا لفظ شدید آواز پر بھی دلالت کرتا ہے(فتح البیان سورۃ القارعۃ ابتدائیۃ) اور میں نے ان معنوں پر زیادہ زور دیا تھا کیونکہ یہ معنے اگلی آیات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے.چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن انسان ان ٹڈیوں کی طرح ہوجائیں گے جو پراگندہ کردی جاتی ہیں اور ٹڈیوں کو ڈرانے اور منتشر کرنے کے لئے سب سے بڑی چیز جس سے کام لیا جاتا ہے وہ آواز ہی ہے.جب ٹڈی آتی ہے تو لوگ خالی پیپے لے کر انہیں ڈھم ڈھم بجانا شروع کردیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ٹڈی آواز سے ہی منتشر کی جاسکتی ہے کسی اور چیز سے نہیں.کہا جاتا ہے کہ ٹڈی کی نظر تیز نہیں ہوتی لیکن اس کے کان بہت تیز ہوتے ہیں اس لئے ٹڈی کو ڈرانے کے لئے شدید آواز پیدا کی جاتی ہے.جب تیز آواز پیدا ہو تو ٹڈی بے تحاشا اڑنے لگتی ہے.شہروں اور دیہات دونوں میں یہ دستور ہے کہ جب ٹڈی کھیتوں پر آکر گرتی اور فصلیں تباہ کرنے لگتی ہے تو بےتحاشا ڈھول اور پیپے بجائے جاتے ہیں.اسی طرح گورنمنٹ کی طرف سے یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ جہاں ٹڈی دل گرا ہو اس کے آگے کچھ دور پر بڑی بڑی کھائیاں کھود دی جاتی ہیں اور مزدور اپنے ہاتھ میں ٹوکریاں اور کدالیں لے کر وہاں کھڑے رہتے ہیں.پھر ڈھول وغیرہ بجا کر ٹڈی کو اڑایا جاتا ہے.چونکہ چھوٹی ٹڈی زیادہ نہیں اڑ سکتی وہ آواز سے ڈر کر اڑتی اور کھائیوں میں گرجاتی ہے اس وقت ڈھول بجانے بند کردیئے جاتے ہیں اور مزدور جو ٹوکریاں اور کدالیں لئے وہاں کھڑے ہوتے ہیں فوراً ان کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں.اسی طرح آج کل بموں کے ذریعہ ٹڈی دل کو منتشر کیا جاتا ہے.جہاں ٹڈی آئے وہاں بم گرا کر ایک ہیبت ناک آواز پید اکی جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹڈیاں اڑتی ہیں اور سامنے کی خندقوں میں گرجاتی ہیں جہاں انہیں دفن کردیا جاتاہے.بہرحال ٹڈی جہاں نقصان پہنچانے کے لئے آئی ہوئی ہو وہاں ڈھول کے ذریعہ یا پیپوں کے ذریعہ یا بموں کے ذریعہ آواز پیدا کی جاتی ہے جس سے ڈر کر ٹڈی اپنی جگہ کو چھوڑ دیتی ہے.پس يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ کے یہ معنے ہوئے کہ اس وقت ایک شدید آواز پید اکی جائے گی جو ایسی ہیبت ناک ہوگی کہ جس طرح ٹڈیاں جب ان کو منتشر کرنے کے لئے ڈھول بجائے جاتے یا پیپے بجائے جاتے یا بم گرائے جاتے ہیں تو وہ ڈر کر اپنے اس حملہ کو جو انہوں نے کھیتوں پر یا درختوں پر یا سبزہ پر کیا ہوتا ہے بھول جاتی ہیں اور اپنے اجتماع کی جگہوںکو چھوڑ دیتی ہیں.اسی طرح جب وہ قارعہ آئے گی تو لوگ لشکروں کی صورت یا اجتماعی صورت کو چھوڑ کر ادھر ادھر دوڑنے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ آج ہمارے لئے بھاگنے کے سوا نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں.پھر فَرَاشٌ کے ایک معنے مَا یَبِسَ بَعْدَ الْمَاءِ مِنَ الطِّیْنِ عَلَی الْاَرْضِ کے بھی ہیں.یعنی بارش برسنے
Page 177
کے بعد زمین پر جو پپڑیاں جم جاتی ہیں ان کو بھی فَرَاشٌ کہا جاتا ہے.دوسری طرف یہ بتایا جاچکا ہے کہ مبثوث کے ایک معنے غبار اڑانے کے بھی ہیں کیونکہ جب بَثَّ الْغُبَارَ کہا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں ھَیَّجَہٗ غبار کو زمین سے اٹھایا.ان معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ کے یہ معنے ہوں گے کہ جس طرح پانی گرتا ہے تو بعد میں پپڑیاں جم جاتی ہیں مگر پپڑی کوئی مضبوط چیز نہیں ہوتی بظاہر وہ سخت نظر آتی ہے مگر چونکہ اس کا حجم بہت معمولی ہوتا ہے اس لئے جب اس پر گھوڑا دوڑایا جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کر غبار کی صورت اختیار کرلیتی ہے.اسی طرح جب وہ قارعہ آئے گی تو لوگ اس طرح اڑ جائیں گے جس طرح غبار اڑجاتا ہے.اسی طرح يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ کے ایک یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ جس طرح پروانہ ایک ہلکاپھلکا سا وجود ہے اسی طرح وہ اس چوٹ سے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوکر ہوا میں اڑجائیں گے کہ یوں معلوم ہوگا وہ پتنگے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں.یعنی وہ قارعہ ایسی ہوگی کہ جب گرے گی چلتے پھرتے خوبصورت انسان ریزہ ریزہ ہوکر ہوا میں اس طرح اڑ جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ کہاں گئے.ان کی شکل انسانوں کی سی نہیں رہے گی.یوں معلوم ہوگا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پروانے ہیں جو ہوا میں اڑ رہے ہیں.وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِؕ۰۰۶ اور پہاڑ اس پشم کی مانند ہوجائیں گے جو دھنکی ہوئی ہوتی ہے.حلّ لُغات.اَلْعِھْنُ.اَلْعِھْنُ: اَلصُّوْفُ اَوِالْمَصْبُوْغُ اَلْوَانًا.عِھْنٌ کے معنے صوف کے بھی ہوتے ہیں اور عِھْنٌکے معنے کئی رنگوں میں رنگی ہوئی اون کے بھی کئے جاتے ہیں (اقرب).مَنْفُوْشٌ دھنکی ہوئی روئی یا پراگندہ کی ہوئی اون کو کہا جاتاہے.چونکہ اون جڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس وقت تک بننے کے کام نہیں آسکتی جب تک اس کے بال بال الگ نہ کئے جائیں.اس لئے عورتوں کا طریق ہے کہ وہ بیٹھ جاتی ہیں اور انگلیوں سے اون کے بالوں کو نوچ نوچ کر الگ کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل ہلکی پھلکی ہوجاتی ہے.چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے مَدَّہٗ حَتّٰی یَتَجَوَّفَ اون کو کھینچ کھینچ کر اس میں جوف پید اکردیاگیا اور اقرب میں لکھاہے نَفَشَ الْقُطْنَ وَالصُّوْفَ نَفْشًا: شَعَّثَہٗ بِالْاَصَابِـعِ حَتّٰی یَنْتَشِـرَ.(اقرب) اس نے انگلیوں کے ساتھ روئی یا اون کو پراگندہ کیا یہاں تک کہ وہ پھیل گئی.پس وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ کے معنے یہ ہوئے
Page 178
کہ پہاڑ اس دن اس پشم کی مانند ہوجائیں گے جو دھنکی ہوئی ہو.تفسیر.اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کیفیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ عذاب ایسا شدید ہوگا کہ ایک طرف انسانوں پر اس کایہ اثر ہوگا کہ اگر وہ لشکر کی صورت میں ہوں گے تو پراگندہ ہوجائیں گے اور سمجھیں گے کہ اجتماع کی صورت ہمارے لئے خطرناک ہے اور اگر وہ شہروں میں بستے ہوں گے تو اس عذاب کے ہیبت ناک اثرات کی وجہ سے وہ شہروں میں نہیں رہیں گے بلکہ گھروں سے نکل کر جنگلوں میں بھاگ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارے لئے نجات کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ہم منتشر اور پراگندہ ہوجائیں.دوسری طرف مصیبت کے لحاظ سے یہ اتنی خطرناک ہوگی کہ لوگ اندھے ہوجائیں گے جس طرح اندھیرے میں پروانے بھاگتے ہیں تو ان کو کوئی رستہ نہیں ملتا.وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اسی طرح ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا اور وہ مارے مارے پھریں گے اور یا پھر یہ حملہ اتنی شدت کا ہوگاکہ انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوجائیں گے.گویا اوّل تو پراگندہ ہوجائیں گے لیکن اگر وہ پراگندہ نہ ہوئے اور لشکر کی صورت میں کسی مقام پرجمع ہوئے یا شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نہ بھاگے تو یہ عذاب ایسا شدید ہوگا کہ ان کی بوٹیاں تک ہوا میں اڑ جائیں گی ا ور یوں معلوم ہوگا کہ پتنگے ادھر ادھر اڑ رہے ہیں.پھر کچھ لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے کہ شاید ہمیں وہاں امن مل سکے.مگر یہ عذاب اتنا خطرناک ہوگا کہ پہاڑوں پر گرے گا تو وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیںگے.اَلْقَارِعَةُ سے مراد ایٹم بم میں پہلے خیال کیا کرتا تھا کہ ان آیات میں توپ خانوں اور موجودہ زمانہ کی ان ہلاکت آفرین ایجادوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن سے عام طور پر لڑائیوں میں کام لیا جاتا ہے مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ اَلْقَارِعَةُ سے ایٹم بم مراد ہے اور اس عذاب کی ساری کیفیت ایسی ہے جو ایٹم بم سے پیدا شدہ تباہی پر پوری طرح چسپاں ہوتی ہے.یہ بم ایسا خطرناک اور تباہ کن ہے کہ اس سے بچنے کی سوائے اس کے اور کوئی صورت نہیںکہ لوگ منتشر اور پراگندہ ہو جائیں.یہ بم جس جگہ گرتا ہے سات سات میل تک کا تمام علاقہ خس و خاشاک کی مانندجلا کر راکھ کر دیتا ہے.بلکہ ایٹم بم کے متعلق اب جو مزید تحقیق ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ سات میل کا بھی سوال نہیں چالیس چالیس میل تک یہ ہر چیز کو اڑا کر رکھ دیتا ہے.ہیروشیما پر اٹومک بم گرایا گیا توبعد میں جاپانی ریڈیو نے بیان کیا کہ اس بم سے ایسی خطرناک تباہی واقعہ ہوئی ہے کہ انسانوںکے گوشت کے لوتھڑے میلوں میل تک پھیلے ہوئے پائے گئے ہیں.یہ بالکل وہی حالت ہے جس کا قرآن کریم نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے کہ انسانوں کا وجود تک باقی نہیں رہے گا.ہڈی کیا اور بوٹی کیا سب باریک ذرات کی طرح ہو جائیں گے اور پتنگوں کی مانند ہوا میں اڑتے
Page 179
پھریں گے.یہی حال اس عذاب کے نتیجہ میں پہاڑوں کا ہو گا.ابھی تک پہاڑوں کے متعلق ایٹم بم کا تجربہ نہیں کیا گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں اس قسم کی ترقی ہو گی کہ پہاڑ بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے.جہاں تک پھیلائو کا سوال ہے یہ بم کسی چیز کو نہیں چھوڑتالیکن جہاں تک گہرائی کا سوال ہے ابھی ماہرین کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی لیکن امید کی جاتی ہے کہ اس بم کو ترقی دے کر ایسا خطرناک بنا دیا جائے گا کہ پہاڑوں اور قلعوں کو بھی ایک آن میں اڑا دے گا.اَلْقَارِعَةُ کے ایک معنے قیامت کے بھی کئے گئے ہیں اور یہی لفظ ہے جو ہیرو شیما اور ناگاساکی پر بم گرائے جانے کے بعدآج تک متواتر استعمال کیا جارہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی جنگ نہ چھوڑی گئی تو اس کے معنے یہ ہیں کہ دنیا پر قیامت آگئی.بعض نے کہا ہے کہ اس کے نتیجہ میں انسانی وجود ہی مٹ جائے گا اور بعض نے کہا ہے ممکن ہے انسانی وجود تو باقی رہے مگر یہ یقینی امر ہے کہ موجودہ تہذیب کا نام ونشان تک باقی نہیں رہے گا.کیونکہ شہر مٹ جائیں گے.قصبات برباد ہو جائیں گے دیہات تباہ ہو جائیں گے اور جو تھوڑے بہت متنفس باقی رہیں گے وہ جنگلوں میں اپنی زندگی کے دن گذارنے لگیں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس بم کو آزادانہ استعمال کیا گیا تو ایسی خطرناک تباہی دنیا میں واقعہ ہو گی کہ وہ لوگ جو نسل انسانی میں سے باقی رہیں گے اس بات سے بھی ناواقف ہو جائیں گے کہ آگ کس طرح جلائی جاتی ہے کیونکہ کارخانے مٹ چکے ہوں گے.علم وفن کے جاننے والے سب تباہ ہو چکے ہوں گے اور غم کے اثرات زائل کرنے کے لئے لوگ اپنی گذشتہ روایات کو بھی فرا موش کر دیں گے تب لوگ ایک بار پھر چقماق سے کام لینا شروع کر دیں گے.پھر وہی دور دنیا میں آجائے گا جو اس دور تہذیب سے پہلے ایک دفعہ آچکا ہے.پھر نئے سرے سے ایجادات عمل میں آئیں گی.اور پھر ایک لمبے عرصہ کے بعد دیا سلائی ایجاد کی جائے گی غرض لوگوں نے ابھی سے اس قسم کے نقشے کھینچنے شروع کر دیئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ میں ایٹم بم کا ہی نقشہ کھینچا گیا ہے اور واقعہ میں ایسی خطرناک تباہی دنیا میں اور کون سی ہو سکتی ہے کہ صرف دو بموں سے اس قدر بڑی حکومت نے جس کے پاس اب بھی نوّے لاکھ فوج تھی ہتھیار ڈال دئیے اور اتحادیوں کے سامنے اسے اپنا سر جھکانا پڑا.جَبَلٌ کے معنے سردار قوم اور بڑے آدمی کے بھی ہوتے ہیں(اقرب).ان معنوں کے رو سے آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ اس دن بڑے بڑے آدمی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے یعنی ان کی طاقت زائل ہو جائے گی.اور وہ کھوکھلے ہو جائیں گے یہ ظاہر ہے کہ بڑے آدمیوں کی بڑائی ان کی انتظامی قابلیت میں ہوتی ہے لیکن اس قسم کے
Page 180
خطرناک ہتھیاروں کے مقابلہ میں تدبیراور کوشش بے کار جاتی ہے اور لیڈروں کی عظمت اور ضرورت مٹ جاتی ہے.فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗۙ۰۰۷فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍؕ۰۰۸ اس وقت جس کے (اعمال کے) پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو (بہترین اور) پسندیدہ حالت میں ہوگا.وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗۙ۰۰۹فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌؕ۰۰۱۰ اور جس کے (اعمال کے) پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانا تو ہاویہ (ہی ) ہوگا.حلّ لُغات.مَوَازِیْن: مِیْزَانٌ کی جمع ہے اور میزان اس ترازو کو کہتے ہیں جس سے چیزیں تولی جاتی ہیں.اسی طرح میزان کے ایک معنے اَلْعَدْ لُ کے ہیں یعنی جزاء اور مثل کے اور میزان مقدار کو بھی کہا جاتا ہے (اقرب).اَلْاُمُّ: اَلْوَالِدَۃُ.اُمٌّ کے معنے ماں کے ہیں اُمُّ الشَّیْءِ اَصْلُہٗ یعنی اُمُّ الشَّیْءِ سے مراد کسی چیز کی اصل یعنی جڑ ہوتی ہے اُمُّ الدَّمَاغِ وَاُمُّ الرَّأْسِ: اَلْـجَلْدَۃُ الَّتِیْ تَـجْمَعُ الدِّمَاغَ اور اُمُّ الدَّمَاغِ اور اُمُّ الرَّأْسِاس جھلی کو کہتے ہیں جو دماغ کو گھیرے ہوئے ہے اُمُّ اَرْبَعٍ وَّ اَرْبَعِیْنَ دُوَیْبَۃٌ سَامَّۃٌ اور اُمِّ اَرْبع ایک زہریلا کیڑا ہوتا ہے جسے ہماری زبان میں ہزار پایا کہتے ہیں.(اقرب) ھَاوِیَۃٌ: ھَوٰی سے ہے اور ھَوَی الرَّجُلُ کے معنے ہوتے ہیں مَاتَ مرگیا.پس ھَاوِیَۃٌ کے معنے ہوئے مرنے والی.اور ھَوَی الشَّیْءُ کے معنے ہوتے ہیں سَقَطَ مِنْ عُلُوٍّ اِلٰی اَسْفَلَ.اوپر سے نیچے کی طرف گرگیا.اس لحاظ سے اُمُّهٗ هَاوِيَةٌ کے یہ معنے ہوںگے کہ اس کی ماں یا اصل (جیسا کہ اُمُّ الشَّیْءِ کے معنے اَصْلُہٗ کے بیان کئے جاچکے ہیں ) هَاوِيَةٌ ہوگی یعنی نیچے کی طرف جانے والی ہوگی.بالفاظ دیگر یوں کہہ لوکہ تنزّل کی حالت اس کی ماں ہوگی یعنی تنزّل کا بیج اس کے اندر پایا جائے گا اور وہ بیج اسے نیچے ہی نیچے گراتا جائے گا.هَاوِيَةٌ جہنم کا نام بھی ہے (اقرب) اور اَلْھَاوِیَۃُ کے معنے ہیں اَلثَّاکِلَۃُ رونے والی (اقرب).تفسیر.قرآن کریم میں مِیْزَان کا لفظ بھی آتا ہے اور مَوَازِیْن کا بھی.خدا تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہوئی ہے تو میزان کا لفظ آیا ہے لیکن بندوں کے لئے جب استعمال ہوا ہے تو موازین کا لفظ استعمال ہواہے.دنیا میں تو کئی دوسری میزانیں بھی ہیں.ہزاروں ہزار آدمی تول رہا ہے اور ہزاروں ہزار تلوا رہاہے لیکن قیامت کے دن جب انسانی اعمال کے نتائج ظاہر ہونے لگیں گے اس وقت تلوانے والے تو بہت ہوں گے لیکن
Page 181
تولنے والا ایک ہی ہوگا.اسی حقیقت کو قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ کے الفاظ میں بیان کیا ہے یعنی اس روز تمام انسانی مالکیتیں ختم ہوجائیں گی صرف ایک خدا کی مالکیت کاکامل ظہور ہوگا.پس چونکہ اپنے اعمال کا وزن کرانے والے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے بندوں کے لحاظ سے قرآن کریم مَوَازِیْن کا لفظ استعمال کرتا ہے اور چونکہ وزن کرنے والا ایک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے مِیْزَان کا لفظ استعمال ہوتاہے.یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں قارعہ کا لفظ آیا ہے اس نتیجہ پر دلالت کرنے کے لئے آیا ہے جو خدا تعالیٰ کا ہاتھ انبیاء کے زمانہ میں خود پید افرماتا ہے گویا قارعہ عام عذابوں کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس سے وہ مخصوص عذاب مراد ہوتے ہیں جو انبیاء کی صداقت کا اظہار کرنے کے لئے آئیں.خواہ بلا واسطہ آئیں یا بالواسطہ.اور جن کے پس پشت خدا تعالیٰ کا ہاتھ کام کررہا ہوتا ہے.زیر تفسیر آیت میں فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ.فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ.وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ.فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ کے الفاظ اسی قارعہ کے انجام پر دلالت کرنے کے لئے آئے ہیں کیونکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے پیچھے خدائی مشیت کا ہاتھ کام کررہا ہے.جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کے ان لشکروں کا حملہ اپنی طرف منسوب کیا جو انہوں نے کفار پر کیا تھا.جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طاغیہ کو اپنی طرف منسوب کیا جو قوم ثمود کی ہلاکت کا موجب ہوئی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شدید ہوا کو اپنی طرف منسوب کیا جو عاد کی تباہی کا موجب ہوئی کیونکہ یہ سب عذاب خدائی مشیت اور اس کے ارادہ کے ماتحت آئے تھے.اسی طرح اللہ تعالیٰ اس جگہ قارعہ کو اپنی طرف منسوب کرکے اس کے نتائج کا اعلان فرماتا ہے کیونکہ یہ قارعہ خدائی پیشگوئیوں کے ماتحت آیا ہے.اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہامات کے ذریعہ پہلے سے خبر دے دی تھی کہ ’’کئی نشان ظاہر ہوں گے.کئی بھاری دشمنوں کے گھر ویران ہوجائیں گے وہ دنیا کو چھوڑ جائیں گے.ان شہروں کو دیکھ کر رونا آئے گا وہ قیامت کے دن ہوں گے.زبردست نشانوں کے ساتھ ترقی ہوگی‘‘.(تذکرہ صفحہ ۶۰۷،۶۰۸) ان الہامات کے ذریعہ چونکہ اس عذاب کی خبر پہلے سے دی جاچکی تھی اس لئے گو ایٹم بم کو ایجاد کرنے والے بندوں کے ہاتھ تھے مگر اس کو منسوب خدا تعالیٰ کی طرف ہی کیا جائے گا.جیسے صحابہؓ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو سزا دلوائی مگر قرآن کریم میں اسے قارعہ قرار دیا گیا.کیونکہ وہ عذاب خدائی سکیم کے ماتحت کفار پر نازل ہوا تھا.بہرحال جو بلا اور مصیبت اتفاقی حادثہ نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی کسی سکیم اور پیشگوئی کے ماتحت آئے اس کے لئے قارعہ کا
Page 182
لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ اس قسم کے عذاب کے جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں ان کے پیچھے الٰہی مشیت کام کررہی ہوتی ہے.اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وہ قوم جس کا پلڑابھاری ہوگا وہ تو راحت و آرام کی زندگی بسر کرے گی لیکن وہ قوم جس کاپلڑا ہلکا ہوگا وہ تباہ و برباد کردی جائے گی.جیسے آج اتحادی کہتے ہیں کہ ہمارا پلڑا بھاری ہوگیا اس لئے ہم جیت گئے اور محوری طاقتیں کہتی ہیں کہ ہمارا پلڑا ہلکاہوگیا اس لئے ہم ہارگئے.پلڑا بھاری ہونے کے یہ بھی معنے ہیں کہ جن کے جہازوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ جیت جائیں گے.یہ محاورہ اس زمانہ میں بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور حکومتیں اپنے اعلانات میں ہمیشہ کہتی رہتی ہیں کہ ہمارے جہازوں کی اتنی ’’ٹنیج‘‘ ہے یعنی اتنا وزن ہے یا اتنے ٹن بم ہماری طرف سے دشمن پر گرائے گئے ہیں.بہرحال جن کی ’’ٹنیج‘‘ زیادہ ہوگی یا جن کے پاس دنیوی سامانوں کی دوسروں کے مقابلہ میں کثرت ہوگی فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ان کو فتح ہوگی اور وہ مزے اڑائیں گے.وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ لیکن جن کی ’’ٹنیج‘‘ کم ہوگی وہ ہاویہ میں گرائے جائیں گے.جیسے جاپان کے بادشاہ نے کہا کہ ہماری شکست کی بڑی وجہ ہمارے سامانوں کی کمی ہے.ہٹلر نے بھی یہی کہاکہ سامانوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ اس وقت بہادری اور جسمانی طاقت کا زور نہ رہے گا.شکست و فتح کا سارا انحصار اس زمانہ میں سامانوں کی کثرت اور ان کی قلت پر آرہے گا.جن کی ’’ٹنیج‘‘ بڑھ جائے گی وہ جیت جائیں گے اور جن کی ’’ٹنیج‘‘ کم ہوگی وہ ہارجائیں گے.اَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗسے مراد یہ تو اس آیت کے ایک معنے ہوئے قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ کے الفاظ ان لوگوں کی نسبت استعمال کئے جاتے ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہوں اور خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ کے الفاظ ان لوگوں کی نسبت استعمال ہوتے ہیں جن کی نیکیاں کم ہوں.اس لحاظ سے دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جیت جائیں گے اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ ہارجائیں گے.گویا دو نتائج ظاہر ہوں گے دنیوی مقابلہ کے وقت جن کے پاس دنیوی سامان زیادہ ہوں گے وہ جیت جائیں گے اور جن کے پا س دنیوی سامان کم ہوں گے وہ ہارجائیں گے اور روحانی مقابلہ کے وقت جن کے روحانی کام، کام کہلانے کے مستحق ہوں گے وہ جیت جائیں گے اور جن کے روحانی کام، کام کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے وہ شکست کھاجائیں گے.پہلی فتح مادیات کے وزن پر ہوگی اور دوسری فتح روحانیات کے وزن پر ہوگی.میں نے اس سورۃ کے شرو ع میں بتایا تھا کہ اس میں اسلام کی دوبارہ ترقی کا ذکر کیا گیا ہے او ربتایا گیا
Page 183
ہے کہ آخری زمانہ میں جب اسلام پر مصیبت اور تکالیف کے دن آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پید اکردے گا جن کے نتیجہ میں اسلام کو فتح حاصل ہوگی.چنانچہ یہ آیات میرے اس دعویٰ کی تائید کرتی ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زمانہ میں فساد اور کفر کا غلبہ دیکھ کر تمہیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے.جب لوگ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے میں مصروف ہوجائیں گے.شدید لڑائیاں لڑی جائیں گی اور بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ جائیں گی اس وقت جہاں ہم دنیوی مقابلہ میں ان لوگوں کو غلبہ دیں گے جن کے پاس دنیوی سامانوں کی فراوانی ہوگی وہاں روحانی مقابلہ میں ہم ان لوگوں کی ذرا بھی پروا نہیں کریں گے اور صرف ان لوگوں کو فتح عطا فرمائیں گے جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا.جب دنیوی مقابلہ میں وہی قوم جیت سکتی ہے جس کے پاس دنیوی سامان زیادہ ہوں تو روحانی مقابلوں میں وہ قوم کس طرح جیت سکتی ہے جس کے پاس روحانی سامان کم ہوں.اصول تو آخر دونوں جگہ ایک ہی کارفرما ہوگا.جس طرح دنیوی مقابلہ کے وقت میزان کا بھاری ہونا کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح روحانی مقابلہ کے وقت صرف اسی قوم کو فتح حاصل ہوسکتی ہے جس کے پاس روحانی سامان زیادہ ہوں.وہ قوم کبھی فاتح نہیں ہوسکتی جس کے پاس روحانی سامانوں کی قلت ہو.اس آیت میں گو ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ کے مقابلہ میں خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جس کے معنے یہ ہیں کہ ان کے پاس وزن تو ہوں گے مگر کم.لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے پاس کچھ بھی وزن نہیں ہوگا.چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا (الکہف: ۱۰۶) ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے.پس چونکہ ایک جماعت کے پاس روحانی سامانوں کی فراوانی ہوگی اور دوسری جماعت کے پاس روحانی سامانوں کا کلیۃً فقدان ہوگا اس لئے وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوں گے اور جنہیں اس کا قرب حاصل ہوگا ان کا پلڑا تو بھاری ہوجائے گا مگر جن کے وزن بہت کم ہوں گے یا جن کے وزن ہوں گے ہی نہیں ان کا پلڑا ہلکا ہوجائے گا.گویا پہلے ان لوگوں کا پلڑا بھاری ہوگا جو دنیوی سامان اپنے پاس زیادہ رکھتے ہوں گے اور ان لوگوں کا پلڑا ہلکا ہوگا جو دنیوی سامان اپنے پاس کم رکھتے ہوں گے.پھر ہم روحانی جنگ کا نتیجہ ظاہر کریں گے اور وہ بھی اسی اصول پر.یعنی جن کی روحانیت بڑھی ہوگی جو تقویٰ اور خدا ترسی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوں جن کی رات اور دن یہی کوشش ہوگی کہ خدا تعالیٰ کا نام بلند ہو اور اس کے احکام پر عمل لوگوں کا شیوہ ہو.وہ تو فتوحات حاصل کریں گے اور جن کے پاس روحانی سامانوں کی کمی ہوگی یا روحانی سامان کلی طور پر مفقود ہوں گے وہ خدائی نصرت
Page 184
سے محروم رہیں گے.بہرحال اس وقت دو۲ ہی قسم کے لوگ آرام میں رہیں گے یا تو وہ اقوام جو محنتی اور جفاکش اور بڑے سازو سامان والی ہوں گی یا وہ جو خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی محبوب ہوں گی اور اس کے بالمقابل جن کے وزن ہلکے ہوں گے یعنی ان کے پاس سازوسامان نہ ہوگا.ان کی ماں ہاویہ ہوگی وہ دکھ پائیں گے او ردینی لحاظ سے جو خدا تعالیٰ کے محبوب نہ ہوں گے وہ تباہ ہوں گے.گویا پہلے زیادہ سازوسامان والے جیتیں گے اور پھر ان لوگوں کا پلڑا بھاری ہوگا جن کا روحانی سامانوں کے لحاظ سے کوئی دوسرا شخص مقابلہ نہیں کرسکے گا.چونکہ دنیوی فتح سے یہ شبہ پیدا ہوسکتا تھا کہ شاید انہیں خدائی مدد حاصل ہے اس لئے ثَقُلَتْ اور خَفَّتْ کے الفاظ استعمال فرماکر اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ اس میں خدائی مدد کا کوئی سوال نہیں.ایک کے پاس سامان زیادہ ہوگئے تو وہ جیت گیا اور دوسرے کے پاس سامان کم ہوگئے تو وہ ہار گیا.اگر خدائی مدد ان کے شامل حال ہوتی تو دوسرے مقابلہ میں بھی وہ جیت جاتے مگر دوسرے مقابلہ میں ایسانہیں ہوگا.اس مقابلہ میں وہ فاتح اقوام جو دنیوی مقابلہ کے وقت اپنے مادی سامانوں کی کثرت کی وجہ سے جیت گئی تھیں بری طرح شکست کھائیں گی اور کمزور دکھائی دینے والے لوگ اپنے روحانی سامانوں کی کثرت کی وجہ سے فتح حاصل کرلیںگے.اس جگہ گو محاورہ کے طور پر خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں مگر درحقیقت مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی وزن ہوگا ہی نہیں جو مقابلہ کے وقت ظاہر کرسکیں.کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ لَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا.بہرحال دنیوی مقابلوں میں وہ قوم جیتے گی جس کے پاس دنیوی سامان زیادہ ہوگا اور روحانی مقابلہ میں وہ قوم جیتے گی جس کے پاس روحانی سامان زیادہ ہوگا.یہ دونوں اٹل فیصلے ہیں اس لئے جب ان میں سے ایک ظاہر ہوجائے تو تمہیں دوسرے فیصلہ کے متعلق بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ جلدی ظاہر ہوجائے گا.ترقی اور تنزّل کے بنیادی وجوہ کا ذکرکرنے کے بعداب اللہ تعالیٰ یہ بتاتاہے کہ وہ قوم جس کی میزان ہلکی ہوگی اس کی کیا حالت ہوگی.فرماتا ہے اُمُّهٗ هَاوِيَةٌ اس کی ماں ہاویہ ہوگی.اُمُّهٗ هَاوِيَةٌ کے چند مطالب هَاوِيَةٌ کے ایک معنے جیسا کہ حل لغات میں بتایا جاچکا ہے تنزّل کے ہوتے ہیں.اس لحاظ سے اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ تنزّل کی حالت اس کی ماں ہوگی یعنی اس کے اندر تنزّل کا بیج پایا جائے گا جس طرح ماں سے آئندہ نسل کا سلسلہ چلتا ہے اسی طرح تنزّل صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوگا بلکہ آئندہ نسلوں تک بھی اس کا اثر پہنچے گا.درحقیقت تنزّل د ور نگ کاہوتاہے.ایک تنزّل کسی قوم یا فرد کی ذات تک
Page 185
محدود رہتا ہے اور ایک تنزّل وہ ہوتا ہے جو بیج کے طور پر آئندہ نسل میں بھی ظاہر ہوتا ہے.اُمُّهٗ هَاوِيَةٌ میں اسی دوسرے تنزّل کی طرف اشارہ کیا گیاہے کہ جس طرح ماں بچے پیدا کرتی ہے اسی طرح وہ قوم جس کی میزان ہلکی ہوگی اس کے گرنے کی حالت ترقی کرتی چلی جائے گی یعنی جو قومیں اس عذاب کے نیچے آئیں گی ان کاتنزّل شروع ہوجائے گا اور پھر وہ تنزّل بڑھتا چلا جائے گا.اُمُّهٗ هَاوِيَةٌ کے ایک یہ بھی معنے ہیں کہ اس کی ماں اس پر روئے گی یعنی وہ قوم بالکل تباہ و برباد ہوجائے گی.عربی زبان میں یہ محاورہ ہے کہ کہتے ہیں ثَکُلَتْکَ اُمُّکَ تیری ماں تجھ کو روئے.چونکہ هَاوِيَةٌ کے ایک معنے ثَاکِلَۃٌ کے بھی ہیں پس اُمُّهٗ هَاوِيَةٌ کے معنے ہوئے اس دن اس کی ماں اس پر روئے گی یعنی وہ بالکل تباہ ہوجائے گی.یوں تو رونے والے اور بھی ہوسکتے ہیں بیٹے بھی ہوسکتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوسکتی ہیں، بیوی بھی ہوسکتی ہے لیکن محاورہ میں صرف ثَکُلَتْکَ اُمُّکَ کہا جاتاہے جس میں حکمت یہ ہے کہ ایک موت وہ ہوتی ہے جو طبعی عمر کے بعد آتی ہے اور ایک موت وہ ہوتی ہے جو طبعی عمر سے پہلے آجاتی ہے.جب کوئی شخص طبعی عمر پاکروفات پاتا ہے تو اس کے ماں باپ پہلے مرچکے ہوتے ہیں اس لئے وہ اس پر نہیں رو سکتے.اس پر اس کے بیوی بچے روتے ہیں.لیکن جب کوئی غیرطبعی وفات پائے تو ما ں باپ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اس پر رونا پڑتا ہے.پس اُمُّهٗ هَاوِيَةٌ کے معنے یہ ہیں کہ وہ لوگ غیرطبعی موت مریں گے، بے وقت کی موت ان پر آئے گی اور وہ تباہ ہوجائیں گے.چنانچہ دیکھ لو جاپان کی موت کتنی غیرطبعی ہے.جرمنی کی موت کتنی غیر طبعی ہے.قوموں کی زندگی دو دو چار چار سو سال تک ہوتی ہے مگر ان کی مثال تو بالکل ویسی ہی ہوئی جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ؎ پھول تو دو دن بہارِ جانفزا دکھلا گئے حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھاگئے یہ ابھی اپنی ترقی کے خواب ہی دیکھ رہے تھے کہ کچلے گئے.پس فرمایا ان کی ماں ان کو روئے وہ کیسی غیرطبعی موت مرے ہیں.پھر میں نے بتایا تھا کہ اُمُّ الدّماغ اور اُمُّ الرَّأس اس جلد کو بھی کہا جاتا ہے جس نے دماغ کو گھیرا ہوا ہے.اس لحاظ سے اُمُّهٗ هَاوِيَةٌ کے یہ معنے ہوں گے کہ ہاویہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی.ترقی کا انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا.ہلاکت ہی ہلاکت او ربربادی ہی بربادی ان پر چاروں طرف سے مسلّط ہوگی.جس طرح
Page 186
اُمُّ الدّماغ نے دماغ کو چاروں طرف سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے اسی طرح ہلاکت ان کو چاروں طرف سے ڈھانپ لے گی، نجات کا کوئی راستہ ان کے لئے باقی نہیں رہے گا.اس آیت کے یہ بھی معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں ان کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ بندوں کی اصلاح ہو اور وہ اپنے گناہوں سے باز آجائیں.محض انتقام لینا اللہ تعالیٰ کے مدّ ِنظر نہیں ہوتا.اسی حقیقت کو اُمُّهٗ هَاوِيَةٌ میںبیان کیاگیا ہے یعنی ہاویہ ان کی ماں ہوگی.جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا اور ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ(الزّمر: ۷) سے حصہ لیتا ہے اور آخر ترقی پاکر رحم مادر سے باہر آتا ہے.اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی بندوںپر کوئی عذاب نازل ہوتا ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوںکے گند دور ہوجائیں اور وہ عذاب کی ظلمت میں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں تاکہ آخر میں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوجائے اور وہ اس کے مقرب بندوں میں شامل ہوجائیں.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْؕ۰۰۱۱نَارٌ حَامِيَةٌؒ۰۰۱۲ اور (اے مخاطب) تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ (ہاویہ) کیا ہے یہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے.حلّ لُغات.حَامِیَۃٌ: حَـمَی سے ہے اور حَـمَی ا لشَّیْءَ مِنَ ا لنَّاسِ (یَـحْمِیْہِ حَـمْیًا وَ حِـمْیَۃً وَحِـمَایَۃً) کے معنے ہوتے ہیں مَنَعَہٗ عَنْـہُمْ اس کو ان سے روکا اور حَـمِیَ مِنَ ا لشَّیْءِ ( یَـحْمٰی حَـمِیَّۃً)کے معنے ہوتے ہیںاَنِفَ اَنْ یَّفْعَلَہٗ اس نے تکبر کا اظہار کیا.اور حَـمِیَ الشَّمْسُ وَالنَّارُ حَـمْیًا(وَحُـمِیًّا وَ حُـمُوًّا) کے معنے ہوتے ہیں اِشْتَدَّ حَرُّھَا اس کی گرمی تیز ہو گئی.اور حَـمِیَ عَلَیْہِ کے معنے ہوتے ہیں غَضِبَ وہ اس پر غضبناک ہوا (اقرب) پس نَارٌ حَامِيَةٌ کے یہ معنے ہو ئے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جس کی گرمی بے انتہا ہوگی.تفسیر.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَاهِيَهْ.وہ تباہی اور بربادی جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے تجھے کیا پتہ کہ وہ کیا ہوگی یعنی وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ الفاظ سے تم اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے یہ الفاظ با لکل ایٹم بم پر چسپاں ہوتے ہیںکیونکہ اس بم کے گرنے سے اتنی شدید گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ میلوں میل تک لوگ جھلس کر مر جاتے ہیں.یہاںتک کہ اس بم کے اثرات کے نتیجہ میں انسانی جسم کی بناوٹ تک بدل جاتی ہے.جا پانیوں نے اعلان کیا ہے کہ ایٹم بم کے حادثہ سے جو لوگ مجروح ہوئے تھے ہم نے ان کا بہت علاج کیامگر وہ اچھے ہونے میں ہی نہیں
Page 187
آتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے خلیے تک بدل گئے ہیں.اس وقت ایٹم بم کے اثر سے دو لاکھ آدمی جاپان میں بیمار ہیں جو باوجود ہر قسم کے علاج کے اچھے نہیں ہوئے.اسی طرح ایک سائنسدان نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ ان کے جسم کے خلیے با لکل بدل گئے ہیںاس لئے آئندہ ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی آنکھیں نہ ہوں کسی کے کان نہ ہوںیا کسی کی دس دس آنکھیں ہوں اور پانچ پانچ سر یا چھ چھ بازو ہوںاور چار چار ٹانگیں، یا ہاتھ ہوں تو پائوں نہ ہوں یا پائوں ہوں تو ہاتھ نہ ہوں یا انسانی نسل کی بجائے کنکھجوروں کی طرح ان کے ہاں اولاد پیدا ہونے لگ جائے کیونکہ ان کے جسم کے خلیے با لکل ٹوٹ چکے ہیں اور اب ان تمام باتوں کا امکان ہے یہ تو ایک سائنسدان کا خیال ہے لیکن اتنا واقعہ خود جاپانیوں نے تسلیم کیا ہے کہ جو لوگ اس حادثہ سے مجروح ہوئے تھے ہم سمجھتے تھے کہ وہ بیمار ہیں علاج سے تندرست ہو جائیں گے لیکن ہزاروں دوائوں کے باوجود ان کے جسم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا.ایسا تغیر ان میں واقعہ ہو چکا ہے کہ خواہ انہیں کوئی دوائی کھلائو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا.اسی طرح نَارٌ حَامِيَةٌ کے ایک یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آگ ان پر غضب کرنے والی ہوگی.نار خود اپنی ذات میںجلانے والی چیز ہے لیکن نار کے ساتھ جب حَامِيَةٌ کا لفظ ملا دیاجائے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ وہ آگ اپنی انتہائی شدت کو پہنچ جائے گی.پس نَارٌ حَامِيَةٌ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم اسے معمولی آگ نہ سمجھووہ ایسی خطرناک ہوگی کہ یوں معلوم ہوگا وہ انتہائی غضب کی حالت میں لوگوں پر حملہ کر رہی ہے.قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے متعلق فرماتا ہے کہ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ (الملک:۹)وہ ایسی شدید ہوگی کہ قریب ہوگا غصہ سے پھٹ جائے.یہی کیفیت نَارٌ حَامِيَةٌ میں بیان کی گئی ہے کہ وہ آگ اس دنیا کی آگ کی گرمی سے سینکڑوں ہزاروں گنے زیادہ گرم ہوگی میں نے سینکڑوں ہزاروں گنے کے الفاظ استعمال کئے ہیں حالانکہ حدیث میں ستّر کا لفظ ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں سات اور ستّر مبالغہ کے لئے استعمال ہو تے ہیں.سات یا ستّر سے سات یا ستّر کے معنے مراد نہیں ہوتے بلکہ بے انتہا زیادہ کے معنے مراد ہوتے ہیں اسی وجہ سے جب بہت زیادتی کی طر ف اشارہ کرناہو تو اکثر سات یا ستّر کا لفظ آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زیادتی صرف سات یا ستّر گنے نہیں ہوتی پس اصل میں صرف بہت زیادہ کا مفہوم بتانا مقصود ہوتا ہے.غرض اَلْقَارِعَةُ وہ عذاب ہے جو موجودہ زمانہ میں ایٹم بم کی صورت میںظاہر ہوا.اور جس کے ہولناک نتائج
Page 188
آج دنیا پر ظاہر ہو چکے ہیں.لیکن ابھی کیا ہے ابھی تو صرف ایک قدم اٹھایا گیا ہے پھر اور ایجادات ہوں گی پھر اور ہوں گی یہاں تک کہ انہی ایجادات کی لپیٹ میں یورو پین اقوام اپنے آپ کو تباہ کر لیں گی.سو سنار کی اور ایک لوہار کی ضرب ا لمثل کے ماتحت آخری حملہ خدا تعالیٰ کا ہو گا اور جن لوگوں کے اعمال کو حقیقی وزن حاصل ہو گا وہ جیت جائیں گے اور دنیا پر ان کو غلبہ و اقتدارحاصل ہو جائے گا.
Page 189
سُوْرَۃُ التَّکَاثُرِ مَکِّیَّۃٌ سورۂ تکاثر یہ مکی سورۃ ہے وَھِیَ ثَـمَانِیَ اٰیَاتٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَفِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے سوا آٹھ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ تکاثر مکی ہے یہ سورۃ جمہور کے نزدیک مکی ہے مگر امام بخا ر ی نے اس سے اختلاف کیا ہے وہ اسے مدنی قرار دیتے ہیں حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے(فتح البیان سورۃ التکاثر ابتدائیۃ ).مستشرقین بھی اسے ابتدائی مکی سورتوں میں سے قرار دیتے ہیں.میرے نزدیک یہ سورۃ مکی ہی ہے کیونکہ اس میں سابق مکی سورتوں کی طرح کی پیشگوئیاں ہیں.صرف مال کا ذکر ہونے کی وجہ سے اسے مدنی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مکہ والوں کے پاس بھی اپنی ملکی دولت کے مطابق مال تھا اور اس میں کافروں کے مال ہی کا ذکر ہے.سورۃ تکاثر کا تعلق پہلی سورتوں سے اس سورۃ کا تعلق پہلی سورتوں سے یہ ہے کہ پہلی سورتوں میں تمام جماعت ہائے کفر کا ذکر کر کے بتایا گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے زمانہ میں بھی اصلاح فرمائیں گے اور آئندہ زمانہ میں بھی.خصوصاً پچھلی دو سورتوں میں ان عذابوں کا ذکر تھا جو کفر کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کے زمانہ میں آنے والے تھے.اب اس سورۃ میں کفر اور خدا تعالیٰ سے دوری کی وجہ بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیوں انسان میں کفر پیدا ہوتا ہے.کیوں اسے خدا تعالیٰ سے بُعد ہوتا ہے اور کیوں لوگ باوجود نبیوں کے ذریعہ حق پا لینے کے آخر دین سے دور چلے جاتے ہیں.سورۃ تکاثر ہزار آیات کے برابر اس سورۃ کے متعلق حاکم اور بیہقی نے ابن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا یَسْتَطِیْعُ اَحَدُکُمْ اَنْ یَّقْرَاَ اَلْفَ اٰیَۃٍ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ قَالُوْا وَ مَنْ یَّسْتَطِیْعُ اَنْ یَّقْرَاَ اَلْفَ اٰیَۃٍ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ قَالَ اَمَا یَسْتَطِیْعُ اَحَدُکُمْ اَنْ یَّقْرَاَ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ (فتح البیان سورۃ التکاثر ابتدائیۃ) یعنی حضرت عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کیا
Page 190
تم میں سے کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا یعنی کیوں ایسا نہیں کرتا کہ وہ ہزار آیتیں روزانہ پڑھ لیا کرے صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ یہ طاقت کس انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ ہزار آیات روز پڑھ سکے.آپؐنے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ روزانہ پڑھ لیا کرے.اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۂ تکاثر کو ہزار آیات کے برابر بتایا ہے.اسی طرح حضرت عمرؓ سے روایت ہے قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ا للہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَاَ فِیْ لَیْلَۃٍ اَلْفَ اٰیَۃٍ لَقِیَ اللہَ وَھُوَ ضَاحِکٌ فِیْ وَجْھِہٖ.قِیْلَ یَا رَسُوْلَ اللہِ وَ مَنْ یَّقْوٰی عَلٰی اَلْفِ اٰیَۃٍ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ اِلٰی اٰخِرِھَاثُمَّ قَالَ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِــیَــدِہٖ اِنَّـــھَــا لَــتَعْدِلُ اَلْفَ اٰیَۃٍ.اَخْرَجَہُ الْـخَطِیْبُ فِی الْمُتَّفَقِ والْمُفْتَرَقِ وَالدَّیْلَمِیْ ( فتح البیان سـورۃ الــتــکاثر ابتدائیۃ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ رات کو ہزار آیات پڑھ لیا کرے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ خدا اسے دیکھ کر خوش ہو گا.صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ یہ طاقت کس انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ ہزار آیات روزانہ پڑھا کرے.اس پر آپ نے سورئہ تکاثر کی تلاوت شروع کر دی یہاں تک کہ آپ اس کے آخر تک پہنچ گئے.پھر آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ سورۃ ہزار آیات کے برابر ہے.(یہ روایت خطیب اور دیلمی دونوں نے نقل کی ہے) ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے زمانے ہوتے ہیں اور دو قسم کے تکاثر ہوتے ہیں.ایک زمانہ میں ایسا تکاثر ہوتا ہے جو قومی زندگی کا موجب ہو جاتا ہے اور دوسرے زمانہ میں ایسا تکاثر ہوتا ہے جو قومی تباہی کا موجب ہو جاتا ہے.چونکہ اس سورۃ میں اس تکاثر کا ذکر کیا گیا ہے جو قومی تباہی کا موجب ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس سورۃ کے مطالب پر عمل پیرا ہو کر اس تباہی سے محفوظ رہ سکتا ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہزار آیات کا قائم مقام قرار دیا ہے.سورۃ تکاثر کو ہزار آیات کے برابر قرار دینے کی وجہ اس جگہ ہزار آیات سے قرآن کریم کا چھٹا حصہ مراد نہیں ( کیونکہ سارے قرآن کی قریباً چھ ہزار آیات ہیں ) بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غرضِ قرآن ہے وہ اس سورۃ میں بیان کر دی گئی ہے کیونکہ عربی زبان میں ہزار سے صرف ہزار کا عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ ان گنت اور بے انتہا چیز کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور ان گنت اور بے انتہا فائدہ انسان اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب وہ اس غرض کو
Page 191
سمجھ جائے جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے سلسلۂ نبوت قائم کیا ہے اورجس کو پورا کرنے کے لئے آدمؑ سے لے کر وہ اپنے مامورین دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجتا رہا ہے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ سورۃ ہزار آیات کے برابر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس سورۃ پر غور کرو اور اس کے مطالب کوہمیشہ اپنے مدــنظر رکھو تو تمہارے متعلق یہ کہا جا سکے گا کہ تم نے اس سورۃ سے وہ فائدہ اٹھا لیا جو سارے نبیوں کی بعثت کی اصل غرض ہے.نبیوں کی بعثت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کا عشق ان میں پیدا کریں.پس جب کوئی شخص اس سورۃ پر غور کرے گا اور حالت سیّئہ سے لوٹ کر حالت طیّبہ کی طرف آئے گا تو لازماً وہ اس مقصد کو حاصل کر لے گا جس کے لئے قرآن کریم نازل ہوا اور جس کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے عالم سے سلسلۂ نبوت قائم فرمایا ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنی کتابوں اور تقریروں میں اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت سرد کر کے خدا تعالیٰ کی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا کریں.پس سورئہ تکاثر نبوت کی اصل غرض بیان کرنے والی سورۃ ہے اور جو شخص اس سورۃ کے مطالب کو اپنے مدّ ِ نظر رکھتا ہے وہ اپنی حالت کو نبیوں کی حالت کے مشابہ بنالیتا ہے.سورۃ تکاثر کے متعلق ایک روایت اس سورۃ کے مضمون کے متعلق بعض اور بھی روایات ہیں چنانچہ عبداللہ بن شخیرؓ بیان کرتے ہیں اِنْتَـھَیْتُ اِلٰی رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہ وَسَلَّمَ وَھُوَ یَقْرَأُ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ وَفِیْ لَفْظٍ وَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَیْہِ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ وَھُوَ یَقُوْلُ.یَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِیْ مَالِیْ وَھَلْ لَّکَ مِنْ مَّالٍ اِلَّا مَا اَکَلْتَ فَاَفْنَیْتَ (یہ روایت مسلم، ترمذی اور نسائی تینوں میں آتی ہے) یعنی میں ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ پڑھ رہے تھے.ایک دوسری روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ قَدْ اُنْزِلَتْ عَلَیْہِ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ آپ پر اس وقت سورئہ تکاثر نازل ہوئی تھی (غالباً اسی روایت سے متاثر ہوکر امام بخاری نے اس سورۃ کو مدنی قرار دیاہے) اور آپ فرمارہے تھے کہ ابن آدم کہتاہے ہائے میر امال.ہائے میرامال.اس کے بعد آپ نے اپنے دماغ میں ایسے انسان کا خیالی وجود مستحضر کرتے ہوئے فرمایا وَھَلْ لَّکَ مِنْ مَّالٍ اِلَّا مَا اَکَلْتَ فَاَفْنَیْتَ.اے اس قسم کے انسان! کیا اس کے سوا تیرا اور بھی کوئی مال ہے جو تو نے کھایا اور ضائع کردیا یعنی تجھے اسی مال سے تعلق ہے جو تو نے کھالیا اور جو تو نے کھالیا وہ باقی تو رہا نہیں.مسلم نے حضرت ابوہریرہؓ سے بھی یہ روایت نقل کی ہے مگر اس میں یہ ذکر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ سورئہ تکاثر اس وقت آپ پر نازل ہوئی تھی.اس حدیث کے الفاظ لمبے ہیں.
Page 192
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُۙ۰۰۲ تم کو ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَؕ۰۰۳ (اور تم اسی طرح غافل رہو گے) یہاں تک کہ تم مقبروں میں جا پہنچو گے.حلّ لُغات.اَلْهٰىكُمُ.اَلْھَاہُ اللَّعْبُ عَنْ کَذَا کے معنے ہوتے ہیں شَغَلَہٗ.لہو و لعب نے اس کو دوسری طرف مشغول کردیا (اقرب) گویا جب کوئی چیز انسان کی توجہ کو ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف پھیر دے تو عربی زبان میں اس کے لئے اَلْہٰی کا لفظ استعمال ہوتا ہے.تَکَاثُرٌ.اَلتَّکَاثُرُ کثرت سے نکلا ہے اور اس کے معنے کثرت میں مقابلہ کرنے کے ہوتے ہیں.چنانچہ تَکَاثَرَ الْقَوْمُ کے معنے ہوتے ہیں کَثُـرُوْا وَ تَغَالَبُوْا فِی الْکَثْـرَۃِ.قوم زیادہ ہوگئی اور دوسروں کے مقابلہ میں اس نے اپنی کثرت پر فخر کیا اور کہا کہ ہم تم سے زیادہ ہیں (اقرب).اسی طرح مفردات میں لکھا ہے اَلْھٰکُمْ اَیْ شَغَلَکُمْ التَّبَارِیْ فِیْ کَثْـرَۃِ الْمَالِ وَالْعِزِّ.تکاثر کے معنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا مقابلہ مال اور عزت کی کثرت میں کرنا یعنی یہ کہنا کہ ہمارا مال زیادہ ہے یا ہماری عزت زیادہ ہے.تم ہمارے مقابلہ میں حیثیت ہی کیا رکھتے ہو.پس اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ کے معنے یہ ہوئے کہ تم کو ایک دوسرے سے مال، عزت اور تعداد میں زیادہ ہونے کے فخر نے غافل کردیا ہے یا بعض دوسری چیزوں سے تمہاری توجہ ہٹاکر اپنی طرف پھیر لیا ہے.تفسیر.اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ کے وسیع مطالب محاورئہ زبان میں ہمیشہ اَلْھٰی کے بعد عَنْ آتا ہے یعنی اَلْھَاہُ عَنْ کَذَا.اسی طرح تکاثر کے بعد فِیْ آتا ہے یعنی جس چیز کے بارہ میں فخرہے اس سے پہلے فِیْ آتا ہے اور جس چیز سے کوئی چیز غافل کردے اس سے پہلے عَنْ آتا ہے.مگر قرآن کریم نے دونوں صلوں کو چھوڑ دیا ہے یعنی اس نے نہ تو یہ کہا ہے کہ تم کو تکاثر نے کسی چیز سے غافل کردیا ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ تمہیں اپنی کسی چیز کی
Page 193
کثرت سے مغرور بنادیا ہے.درحقیقت دونوں صلوں کو چھوڑ دینے سے ایک بہت بڑا مضمون بیان کیا گیا ہے.(۱) اگر اس چیز کا بھی ذکر کردیا جاتا جس سے تکاثر نے ان کو غافل کردیا تھا تو مضمون محدود ہوجاتا اور اس اجمال میں جو فصاحت پائی جاتی ہے وہ جاتی رہتی کیونکہ تکاثر کسی ایک نیک بات سے نہیں بلکہ ہرنیک بات سے انسان کو غافل کردیتا ہے.تکاثر کے معنے ہوتے ہیں ذاتیات کا غلبہ.آخر دنیا میں کیوں ایک انسان دوسرے پر فخر کرتا ہے.اسی لئے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھنے کے وہ اپنی ذات کی بڑائی دیکھنے لگ جاتا ہے.وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اگر اس میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ ہے.اگر اس میں کوئی کمال پایا جاتا ہے تووہ خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے.اس کی نگاہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کرکے صرف ذاتی بڑائی کو اپنے سامنے رکھ لیتی ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اپنے زورِ بازو سے حاصل کیا ہے.پس دوسروں پر فخر کرنے کا سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے سامنے صرف اس کی ذاتی بڑائی رہ جاتی ہے خدا تعالیٰ کا فضل جو تمام ترقیات کا اصل باعث ہوتا ہے اسے بھول جاتا ہے.احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بڑائی بیان کی اور پھر فرمایا میں کوئی فخرنہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ خوبی محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوئی ہے.اس سے ظاہر ہے کہ مومن باوجود بڑائی حاصل ہونے کے تفاخر سے کام نہیں لیتا.کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے لئے موجب فخر ہے وہ مجھے خودبخود حاصل نہیں ہوئی بلکہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے.لیکن غیرمومن ایسا نہیں کرتا اس لئے جب کسی انسان کے اندر تکاثر پیدا ہوگا اور وہ اپنی کثرت پر فخر کرے گا یا اپنی عزت پر فخر کرے گا یا اپنے مال پر فخر کرے گا یا اپنی طاقت پر فخر کرے گا تو لازمی طور پر خدا تعالیٰ کا وجود اس کی نظر سے اوجھل ہوجائے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے.پس تکاثر کی وجہ سے ایک تو خدا تعالیٰ کے فضل انسانی نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں پھر اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی ذات بھی اوجھل ہوجاتی ہے.جو شخص شور مچارہا ہو کہ میں بڑا، میں بڑا.اسے لازمی طور پر اپنے سے بڑا اورکوئی وجود نظر ہی نہیں آتا.ورنہ کیا سورج کے سامنے کھڑے ہوکر بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میرا دیا کتنا روشن ہے؟ رات کے وقت تو لوگ بے شک اپنے لیمپ کی روشنی پر فخر کرسکتے ہیں مگر دن کو نہیں.اور اگر کوئی دن کے وقت بھی اپنے دِئے پر فخر کرتا ہے تو اس کے صاف معنے یہ ہیں کہ سورج اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے ورنہ یہ کس طرح ہوسکتا تھا کہ سورج بھی اسے نظر آتا اور وہ اپنے دِئے پر بھی فخر کرسکتا.اسی طرح جب کوئی شخص اپنی ذات کو دنیا میں بڑا دیکھتا ہے تو اس کا سوائے اس کے او رکوئی مفہوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ سے اوجھل ہوچکا ہے.گویا تکاثر کے نتیجہ میں
Page 194
اوّل موجبات فخر یعنی صفاتِ الٰہیہ اس کی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ خدا تعالیٰ کی ذات بھی اس کی نظر سے اوجھل ہوجاتی ہے.پس اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ کے معنے یہ ہوئے کہ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ عَنْ صِفَاتِ اللہِ وَ عَنِ اللہِ.تمہیں تکاثر نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات دونوں سے غافل کردیا ہے.پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جتنے فضل نازل ہوتے ہیں سب ملائکہ کے ذریعہ نازل ہوتے ہیں.ملائکہ انسان کی ترقی اور اس کو بلند شان تک پہنچانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہیں اور انسان کا فرض ہے کہ اس توسط کو کبھی نظرانداز نہ ہونے دے لیکن جب کوئی شخص اپنی ذات پر فخر کرتا ہے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کو بھول جاتا ہے بلکہ وہ اس بات کو بھی فراموش کردیتا ہے کہ میری عزت یا دولت یا شہرت کے حصول میں محض میری ذاتی کوششوں کا دخل نہیں بلکہ ان ملائکہ کا بھی دخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی کامیابی کے سامان مہیا کرتے ہیں.پھر جب بھی کسی کو بڑائی حاصل ہوتی ہے ہمیشہ اضافی طور پر ہوتی ہے.غیر اضافی طور پر ہمیں دنیا میں کوئی شخص بڑا نظر نہیں آتا.یہ ایک بہت بڑانکتہ ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے مگر بعض بےوقوف اس کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے اعتراض کردیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم بھی عجیب کتاب ہے کہ اس میں کسی جگہ پر تو یہ ذکر آتا ہے کہ فلاں سے بڑا کوئی نہیں اور بعض جگہ کسی اور کو بڑا قرار دے دیا گیا ہے.کوئی ایک تو بڑا ہو سکتا ہے مگر یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ سب لوگ بڑے ہوں.وہ نادان یہ نہیں جانتے کہ اس اعتراض سے خود ان کی اپنی حماقت کا ثبوت ملتاہے.ورنہ قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سراسر حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے.اس کا منشا یہ ہے کہ دنیا میں اگر تمہیں کوئی بڑانظر آتا ہے تو اس کی بڑائی محض اضافی ہے غیراضافی نہیں.کیونکہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو جزئیات کا علم کامل نہیں.ایک قوم دنیا میں بڑھتی اور ترقی کرتی ہے تو وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوجاتی ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال حاصل کرلیا.اتنابڑا کمال کہ مجھ سے پہلے شاید ہی کسی قوم نے حاصل کیا ہو.اسی بناء پر وہ تکبر میں مبتلا ہوجاتی اور اپنے مقابلہ میں دنیا کی تمام اقوام کو حقیر اور ذلیل خیال کرنے لگتی ہے.مگر آہستہ آہستہ جب گذشتہ تاریخی واقعات منکشف ہوتے ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس قسم کے کمالات رکھنے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے تھے.بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق آ ج سے پچاس سال پہلے یورپ اسی امر کا مدعی تھا کہ ہم ان چیزوں کے موجد ہیں.مگر آج یورپ تسلیم کرتاہے کہ ہم سے پہلے یہ چیزیں دنیا میں موجود تھیں.پھر جن زمانوں کی تاریخ کلیۃً مٹ چکی ہے نہ معلوم ان میں کتنی بڑی ایجادات ہوچکی تھیں اور جو تاریخ آئندہ مٹ جائے گی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بعد دنیا کی کیا صورت ہوجائے گی اور وہ کن کن امور پر بے جا فخر کرنے لگ جائیں گی.
Page 195
مختلف علوم میں مسلمانوں کی ایجادات میں انگریزوں کی سرجری سے بڑا متاثر تھا اور میں سمجھتا تھا کہ انہوںنے اس فن میں خوب ترقی کی ہے مگر ایک دن جب کہ میں بقراط کا ایک چھوٹا سا رسالہ سرجری کے متعلق پڑھ رہا تھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی.جب میں نے دیکھا کہ بقراط نے اس رسالہ میں یہ بحثیں کی ہیں کہ میں نے گردوں کے اتنے اپریشن کئے ہیں اور فلاں عضو کے اتنے اپریشن کئے ہیں.پھر اس نے ان آلات کا بھی ذکر کیا ہے جن کے ذریعہ اس نے یہ باریک درباریک اپریشن کئے.اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرجری اس سے پہلے بھی دنیا میں ترقی یافتہ صورت میں موجود تھی.پہلے بھی اپریشن کئے جاتے تھے پہلے بھی مختلف قسم کے آلات ایجاد ہوچکے تھے اور پہلے بھی لوگ ان فنون میں مہارت رکھتے تھے مگر پھر ایک زمانہ ایسا آیا جب یہ علوم دنیا سے مٹ گئے اس لئے کئی ایسی ایجادات جو درحقیقت مسلمانوں کی تھیں ان کے متعلق آج یورپ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے موجد ہیں حالانکہ وہ ان کے موجد نہیں بلکہ ان کے موجد مسلمان لوگ ہیں.اسی طرح جراثیم کا علم موجودہ زمانہ کی طبی تحقیق کا بہترین نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے دنیا کو جراثیم کا علم نہیں تھا لیکن ایک یورپین مصنف نے اپنی ایک کتاب میں اس بات پر بحث کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کہ جراثیم کا علم دنیا میں پہلے موجود نہیں تھا.وہ مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے اس علم کی تحقیق کی اور وہ تحقیق کرتے کرتے اس کی آخری حد تک پہنچ گئے.مگر چونکہ ان کے پاس خوردبین نہیں تھی اس لئے وہ نام نہیں رکھ سکے ورنہ باقی سب کیفیتیں جو جراثیم کے متعلق ہماری طرف سے پیش کی جاتی ہیں انہوں نے دریافت کرلی تھیں.چنانچہ اس نے مثال دی ہے کہ جب دارالسلام (بغداد) کی بنیاد رکھی جانے لگی تو بادشاہ نے ایک طبیب کو اس غرض کے لئے مقرر کیا کہ وہ مشورہ دے کہ دارالسلام کی بنیاد کس مقام پر رکھی جائے.وہ لکھتا ہے بادشاہ کا ایک طبیب مقرر کرنا اور اس سے یہ مشورہ حاصل کرنا کہ دارالسلام کی بنیاد کہاں رکھی جائے بتاتاہے کہ مسلمان بادشاہوں کو طب کا اس قدر علم تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شہر کی بنیاد کا تعلق بھی طب سے ہے.چنانچہ طبیب مقرر ہوا اور اس نے حکم دیا کہ بکرے ذبح کرکے تمام علاقوں میں مختلف جگہوں پر ان کے ٹکڑے رکھ دیئے جائیں.کئی دنوں کے بعد اس نے تمام ٹکڑوں کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ ان کی کیا حالت ہے.آخر اس نے بادشاہ کے پاس رپورٹ کی کہ آپ فلاں جگہ شاہی قلعہ بنائیں.فلاں جگہ چھائونی تیار کریں اور فلاں جگہ لوگوں کے لئے رہائشی مکانات تیار کرائیں کیونکہ ان مقامات پر بکروں کا گوشت یا تو کم سڑا ہے یا بالکل ہی نہیں سڑا اور فلاں فلاں مقامات پر اس میں زیادہ تعفن پیدا ہوا ہے.جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مقامات پر گوشت زیادہ سڑا ہے وہاں کی ہوا میں عفونت زیادہ ہے اور جن مقامات پر گوشت میں
Page 196
سڑاند پید انہیں ہوئی یا بہت ہی کم پیدا ہوئی ہے وہاں کی ہوا زیادہ صاف ہے.اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ یورپین مصنف لکھتا ہے کہ اس سے یہ حقیقت روشن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی کہ آج سے سینکڑوں سال قبل مسلمانوں کو بکٹیریا کا علم حاصل تھا ہم نے صرف خوردبین کے ذریعہ اس کو پکڑ لیا ہے ورنہ جہاں تک علمی تحقیق کا سوال ہے مسلمانوں نے بھی اس کاپتہ لگالیا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہوا کی صفائی کا تعلق بعض غیرمرئی چیزوں کے ساتھ ہے جس جگہ وہ ہوتی ہیں وہاں تعفن پیدا ہوجانے سے انسانی صحت خراب ہوجاتی ہے اور جہاں نہیں ہوتیں وہاں انسان کی صحت اچھی رہتی ہے.پس یہ علم وہ ہے جس کی مسلمانوں نے داغ بیل ڈالی اور اپنے زمانہ میں انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا مگر پھر ان کی اپنی نسلیں بھی بھول گئیں اور باقی دنیا کو بھی یاد نہ رہا کہ اس علم کا کون موجد تھا.چنانچہ آج جب یورپین محققین نے جراثیم کا علم دریافت کیا تو انہوں نے یہ خیال کرنا شروع کردیا کہ اس علم کے اوّلین موجد ہم ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان اس سے پہلے یہ علم حاصل کرچکے تھے.پس جب بھی کوئی فخر کرتا ہے وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت لوگ گذر چکے ہیں اور وہ اپنے اپنے زمانوںمیں بڑی شہرت کے مالک رہے ہیں میرے لئے فخر کا کون سا مقام ہے.پس تکاثر سے کا م لینے والا صرف خدا تعالیٰ کی صفات کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کی ذات کو نظر انداز نہیں کرتا، اس کے ملائکہ کو نظرانداز نہیں کرتا بلکہ دنیا کے سابق علوم اور سابق ایجادات سے بھی انکار کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے باپ دادا تو محض جاہل تھے کمال صرف اسی کو حاصل ہوا ہے.پس تکا ثر کا ایک نتیجہ واقعات کے انکار کی صورت میں رونما ہوتا ہے.پھر اس کے نتیجہ میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے اور غرباء پر ظلم شرو ع ہو جاتاہے.بجائے اس کے کہ انسان کا ذہن اس طرف جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لئے مال دیا ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں اس کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں میرا کام یہ ہے کہ میں دوسروں سے خدمت لوں اور دوسروں کا کام یہ ہے کہ وہ میری غلامی اختیار کریں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ تمام اخلاق فاضلہ اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں.پس چونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیںجن سے تکاثر نے انسان کو محروم کر دینا تھا اس لئے اگر یہ کہا جاتا کہ اَلْھٰکُمُ التَّکَاثُرُ عَنِ اللہِ یا کہا جاتا اَلْھٰکُمُ التَّکَاثُرُ عَنْ صِفَاتِ اللہِ یاکہا جاتا اَلْھٰکُمُ التَّکَاثُرُعَنْ مَلٰٓئِکَۃِ اللہِ یا کہا جاتا اَلْھٰکُمُ التَّکَاثُرُ عَنْ اَنْبِیَآءِ اللہِ یا کہا جاتا اَلْھٰکُمُ التَّکَاثُرُ عَنِ الْاَخْلَاقِ یا کہا جاتا اَلْھٰکُمُ التَّکَاثُرُ عَنِ الْعِبَادَاتِ یا کہا جاتا اَلْھٰکُمُ التَّکَاثُرُ عَنِ التَّارِیْـخِ تو ایک لمبا مضمون بن جاتا اور پھر بھی اپنے بیان میں ناقص اور نا تمام ہی رہتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مجمل الفاظ میں بیان کیا اور اَلْھٰی کے بعد عَنْ کا ذکر نہیں کیا یعنی یہ بیان نہیں کیا کہ
Page 197
تمہیں تکاثر نے کس چیز سے غافل کر دیا ہے تاکہ تمام وہ چیزیں جن سے تکاثر نے غافل کر دیا یا جن سے تکاثر غافل کر سکتا ہے وہ ایک ایک کر کے انسان کے ذہن میں آجائیں اور وہ اس مضمون سے زیادہ سے زیادہ سبق حاصل کرے.غرض اس ابہام میں یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنی باتوں سے تکاثر انسان کو غافل کر دیا کرتا ہے وہ سب کی سب باتیں اس آیت میں شامل ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم کسی ایک نیکی سے نہیں بلکہ سب کی سب نیکیوں سے اس روح مفاخرت کی وجہ سے محروم ہو گئے ہو.پس عَنْ کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اس مضمون کو نہایت وسیع اور شاندار بنا دیا گیا ہے.(۲) دوسرا صلہ فِیْ کا چھوڑا گیا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم کس چیز میں اپنی بڑائی بیان کرتے ہو اور بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہو.اس ابہام میں بھی یہ فائدہ مدّ ِنظر رکھا گیا ہے کہ کفار جہاں تک دنیوی طاقت کا سوال ہے ہربات میں مسلمانوں سے زیادہ تھے.وہ اپنی تعداد پر بھی فخر کرتے تھے.اپنی تجارت پر بھی فخر کرتے تھے.اپنے وسیع تعلقات پر بھی فخر کرتے تھے.اپنے جمع کردہ اموال کی کثرت پر بھی فخر کرتے تھے.اپنے نوجوانوں کی جنگی مہارت پر بھی فخر کرتے تھے.اپنی اعلیٰ سواریوں پر بھی فخرکرتے تھے.اپنے مسحور کر دینے والے شعراء پر بھی فخر کرتے تھے.اپنے گرمادینے والے خطیبوں پر بھی فخر کرتے تھے.اپنے عقل و دانش میں مشہور بوڑھوں پر بھی فخر کرتے تھے.قومی جذبات سے معمور سینوں والی مائوں پر بھی فخر کرتے تھے.قوم کی عزت پر مر مٹنے والے سپاہیوں پر بھی فخر کرتے تھے اور اسی طرح اور بہت سے امور میں مسلمانوںکو اپنے سے ادنیٰ اور کمزور قرار دے کر ان کی تحقیر کرتے تھے اور ان کے دعاوی کو غیرمعقول اور بے ثبوت و دلیل دعاوی قرار دیتے تھے.قرآن کریم جہاں تک ان کے ہر امر میں زیادہ ہونے کا سوال ہے ان کے دعویٰ کو ردّ نہیں کرتا.وہ مانتا ہے کہ عدد میں، مال میں، سامانوں میں، جتھا بندی میں تم زیادہ ہو.لیکن صرف اتنا کہتا ہے کہ ان چیزوں کی زیادتی نے تم کو اخلاق فاضلہ اور دین سے محروم کردیا ہے اور انسان مال اور دولت سے نہیں جیتا کرتا بلکہ اخلاق و انکسار سے جیتا کرتا ہے.پس یہ زیادتیاں اور بڑھوتیاں تمہارے لئے مفید نہیں بلکہ مضر ہیں کیونکہ سامان کم ہوتے تو تم اپنی ترقی کے لئے کوشش کرتے.اب سامانوں کی فراوانی نے تم کو سست اور غافل بنادیا ہے اور ان اخلاق کے کمانے سے محروم کردیا ہے جن کو کمائے بغیر انسان کو پائدار دولت حاصل نہیں ہوا کرتی.اس لئے یہ دولت تم کو نجات نہ دلائے گی بلکہ تمہاری تباہی کا موجب ہوگی.گرتے ہوئے سوار ایک بچے سے بھی کمزور ہوتے ہیں اور بوسیدہ عمارت ایک جھونپڑی سے بھی بےقیمت ہوتی ہے.
Page 198
اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ کے معانی کو محدود کرنے کی کوشش بعض روایات میں اس وسیع المطالب سورۃ کے مضامین کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے.چنانچہ کلبی کہتے ہیں کہ بنوعبد مناف اور بنو سہیم کے درمیان بحث ہوئی کہ اسلام میں کون زیادہ معزز ہے.چنانچہ بنو عبد مناف اور بنو سہیم دونوں نے پہلے اپنے اپنے زندہ سردار اور لیڈر اور جرنیل گنانے شروع کئے.بنو عبد مناف نے کہاکہ ہم میں اتنے سردار ہیں، اتنے قاضی ہیں، اتنے جرنیل ہیں اور اتنے لیڈر ہیں اور بنو سہیم نے اپنے سردار اور قاضی اور لیڈر اور جرنیل گنائے آخر بنو عبد مناف بڑھ گئے.جب بنو سہیم نے دیکھا کہ یہ لوگ زندوں کا مقابلہ کرنے میں ہم سے جیت گئے ہیں تو انہوں نے کہا آئو ہم سے مردوں میں مقابلہ کرلو.دیکھو کہ ہم میں سے زیادہ لوگ اسلام کے لئے قربان ہوئے یا تم میں سے زیادہ لوگوں نے اسلام کے لئے اپنی جانیں قربان کی ہیں.چنانچہ بنو عبد مناف اور بنو سہیم دونوں مقبروں میں گئے اور انہوں نے اپنے اپنے مردے گنانے شروع کئے کہ ہم میں سے اتنے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور تم میں سے اتنے لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے.اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی کہ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ.حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ.تمہیں تکاثر نے اس حد تک غافل کردیا ہے کہ تم قبروں میں گئے اور تم نے مردے گنانے شروع کردیئے.اس روایت کے برخلاف ابوہریرہؓ سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ انصار کے دو قبائل بنو حارثہ اور بنوالحرث نے یہ مقابلہ کیا تھا انہوں نے پہلے اپنے زندہ لیڈر گنوائے اور پھر مردہ (روح المعانی زیر سورۃ التکاثر).لیکن مقاتل اور قتادہ کے نزدیک یہاں نہ بنو عبد مناف اور بنو سہیم کا ذکر ہے نہ بنو حارثہ اور بنو الحرث کا.بلکہ یہاں یہود کا ذکر ہے(فتح البیان زیر سورۃ التکاثر).ان روایات کے تشتت اور اختلاف سے ہی پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قطعی بات ثابت نہیں.اگر ثابت ہوتی تو یہ تین الگ الگ قسم کی روایات کیوں آتیں.کیونکہ بعض کا ذہن انصار کی طرف چلا جاتا بعض کا یہود کی طرف اوربعض کا بنوعبد مناف اور بنوسہیم کی طرف.یہ کہنا کہ اس سورۃ کا شانِ نزول یہی ہے اس کا مطلب جیسا کہ میں نے بارہا بتایاہے صرف اتنا ہے کہ اس واقعہ پر بھی یہ سورۃ چسپاں ہوتی ہے نہ یہ کہ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو نازل فرمایا.ممکن ہے بعض دفعہ بنو حارثہ اوربنو الحرث کا آپس میں اس طرح مقابلہ ہوا ہو اور کسی نے کہا ہو کہ تمہاری تو وہی حالت ہے جو اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ میں بیان کی گئی ہے یا کبھی بنو عبد مناف اور بنو سہیم میں مقابلہ ہوا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہہ دیا ہو کہ تم یہ کیا لغو حرکت کررہے ہو.تمہاری تو وہی مثال ہے جو اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ میں بیان ہوئی ہے.مگر اس کے یہ معنے نہیں ہوسکتے کہ یہ سورۃ ان کے لئے نازل ہوئی تھی کیونکہ قرآن کریم نبوت حقہ کے قیام اور اسلام کے استحکام کے لئے آیا ہے
Page 199
بنوحارثہ اور بنو الحرث یا بنو عبدمناف اور بنو سہیم کے جھگڑوں کے قصے بیان کرنے کے لئے نہیں آیا.ہاں مثال کے طور پر اگر کوئی جھگڑا ہو تو اس پر اس آیت کو چسپاں کیا جاسکتا ہے.مثلاً ہم کبھی بازار جائیں اور دیکھیں کہ ایک دوکاندار دوسرے سے لڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے مقابلہ میں تیری حیثیت ہی کیا ہے.میرے پاس بھینس ہے، میرے پاس گھوڑا ہے، میرے پاس مکان ہے، میرے پاس زمین ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں.اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کیالغو حرکت کررہے ہو تمہیں تو تکاثر نے اعلیٰ اخلاق سے بالکل محروم کردیا ہے.ہمارے اس قول کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ یہ سورۃ صرف تمہارے لئے نازل ہوئی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہوگا کہ اس سورۃ کا مضمون تمہارے اس جھگڑے پر بھی چسپاں ہوتا ہے.پس اس سورۃ کا جو شان نزول بتایا جاتا ہے اس کے معنے صرف اتنے ہیں کہ بعض واقعات صحابہؓ کے زمانہ میں بھی ایسے ہوئے جن پر یہ سورۃ چسپاں ہوتی ہے ورنہ یہ سورۃ اپنے اندر بہت وسیع مطالب رکھتی ہے.اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ.حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ میں ماضی کے صیغے استعمال کرنے کی وجہ چونکہ اس سورۃ میں ماضی کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اس لئے بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سورۃ میں ماضی کے الفاظ کس حکمت کے ماتحت استعمال کئے گئے ہیں اور چونکہ انہوں نے زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کے معنے انسان کے مرجانے اور اس کے قبر میں داخل ہوجانے کے کئے ہیں.اس لئے بعض نے کہا ہے کہ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ.حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ تحقّقِ وقوع کے لئے آیا ہے یعنی تکاثر نے تم کو غافل کردیا یہاں تک کہ تم مرگئے.یعنی چونکہ یہ بات ضرور ہوکر رہنی ہے اور موت ایسی چیز ہے جس سے کسی انسان کو مفر نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کے الفاظ استعمال کئے ہیں.یہ بتانے کے لئے کہ بات ایسی قطعی اور یقینی ہے کہ ہم اس کے مضارع کا صیغہ استعمال کرنے کی بجائے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں.مگر میرے نزدیک یہ بات صحیح نہیں.اس لئے کہ تحقّقِ وقوع کا مسئلہ وہاں چسپاں ہوتا ہے جہاں وقوعہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو مثلاً قرآن کریم نے یہ پیشگوئی کی کہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتیں گے اور مکہ کو ایک دن فتح کرلیں گے.اب مکہ کا فتح ہونا کفار کی نظروں سے بالکل پوشیدہ امر تھا اور وہ اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرسکتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ سمیت مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے اور کفار ان کے زیر نگین آجائیں گے.پس چونکہ یہ بات کفار کی نگاہ میں بالکل غیر ممکن تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دینے کی بجائے ماضی کا صیغہ استعمال کردیا اور بتادیا کہ تم تو اس پیشگوئی کو نہیں مانتے لیکن ہم اسے ایسا قطعی اور یقینی سمجھتے ہیں جیسے ماضی یقینی ہوتی ہے اور جس کے وقوع میں کسی کوکوئی شبہ نہیں ہوتا.لیکن زیارتِ قبور یا
Page 200
قبروں میں داخل ہونا تو ایک ایسی بات ہے جس کا کفار بھی انکار نہیں کرتے تھے اور وہ تسلیم کرتے تھے کہ ہر انسان ایک دن لازماً مرجائے گا.پس اس قاعدہ کا اطلاق یہاں درست نہیں.یہ قاعدہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مخاطب تو انکار کررہا ہو اور متکلم کواپنے کلام پر زور دینا مقصود ہو.بعض اورلوگوں نے یہ معنے کئے ہیں کہ چونکہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہمیشہ دنیا میں قومیں تکاثر کرتی آئی ہیں اور چونکہ دنیا میں زندوں کی نسبت مردے زیادہ ہیں اس لئے کثرت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کردیا ہے.وہ اپنی اس توجیہ کی بنیاد اس امر پر رکھتے ہیں کہ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں بہت سی قومیں گذر چکی ہیں جن کا مجموعی زمانہ کئی ہزار سال کا ہے.پس چونکہ ماضی کی کثرت ہے اس لئے کثرت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کردیا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جس جماعت کوکثرت اور غلبہ حاصل ہو اسی کے مطابق صیغے استعمال کرلئے جاتے ہیں.مثلاً قرآن کریم میں کئی جگہ نماز روزہ کے احکام میں صرف مردوں کا ذکر کیا گیا ہے عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا.لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ عورتیں اس میں شامل ہیں.اسی طرح ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ پہلے لوگ کثیر تھے اور بعد میں آنے والے قلیل ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ.حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کے الفاظ استعمال کئے ہیں.یہ معنے پہلے معنوں سے زیادہ معقول ہیں مگر یہ کہنا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرمیں تشریف لائے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کی نسبت کم ہوں یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیاجاسکتا کہ پہلے ساری دنیا کی بھی اتنی آبادی نہیں تھی جتنی آج صرف ہندوستان کی ہے.پہلے زمانہ میں نہ لوگوں کو امن کی قدر و قیمت معلوم تھی نہ آپس میںمیل جول کی سہولتیں انہیں میسر تھیں، نہ علوم کی کثرت تھی، نہ ایجادات کا دور دورہ تھا، نہ زندگی کو بہتر بنانے کے اصول لوگوں کو معلوم تھے، نہ آبادی کو ترقی دینے کے ذرائع کی انہیں کچھ خبر تھی.اس وقت تمدن بھی ابتدائی حالت میں تھا، اس وقت سیاست بھی ابتدائی حالت میں تھی، اس وقت علم بھی ابتدائی حالت میں تھا اور اس وقت دنیا کا آپس میں وہ رابطہ و اتحاد نہیں تھا جو موجودہ زمانہ میں نہایت وسیع طور پر پایا جاتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ قرار دیا تھا اس لئے آپ کی بعثت کے ساتھ ہی دنیا کی حالت میں ایک غیر معمولی تغیر پیدا
Page 201
ہونا شروع ہوگیا وہ امن جس سے دنیا نا آشنا تھی اس کی قدر و قیمت کا آپ کے ذریعہ لوگوںکو احساس پیدا ہوا.علم کا چاروں طرف چرچا شروع ہوگیا.تمدن اپنے ارتقاء کی منازل بڑی سرعت سے طے کرنے لگا.ذرائع نقل و حرکت میں ایک نیا دور شروع ہوگیا اور دنیا کی آبادی جو پہلے متفرق قبائل کا رنگ رکھتی تھی ایک ملک کا رنگ اختیار کرگئی.قوموں کا قوموں سے اور ملکوں کا ملکوں سے ایک گہرا تعلق قائم ہوگیا.سفر کی سہولتیں میسر آگئیں اور لوگ بڑی کثرت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگ گئے.ان وجوہ کا قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ دنیاکی آبادی بھی پہلے کی نسبت بہت بڑھ گئی اور زمین کو آباد کرنے کے ایسے وسائل نکل آئے جو اس سے پہلے کسی کے واہمہ میں بھی نہیں آئے تھے.پس بے شک یہ درست بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے آخری حصہ میں تشریف لائے ہیں مگر یقینی اور قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ پہلے زمانوں کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں سے اپنی تعداد میں زیادہ تھے.یہ تو ہم کہتے ہیں اور یقیناً کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ میں آئے مگر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ظہور سے لے کر قیامت تک جس قدر مومن اور کافر ہوں گے ان کی تعداد پہلی امتوں کے مومنوں اور کافروں سے کم رہے گی.اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا غالباً یہ بات صحیح نہیں گو قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا.میرے نزدیک یہ سب دور کی کوڑیاں ہیں.اس جگہ مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے اور ان کی دینی و دنیوی پستی اور تباہی کی حقیقت بیان فرماتا ہے اور چونکہ عقلی دلیل ہر جگہ چسپاں ہوسکتی ہے اس لئے اس سے ایک قاعدہ کلیہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور تسلیم کرناپڑتا ہے کہ جو قانون ان کے لئے تھا وہی اگلی قوموں کے لئے بھی ہوگا.مثلاً ہم زید کو کہیں کہ تم زہر نہ کھائو ورنہ مرجائو گے.اب یہ فقرہ تو زید سے کہا گیا ہے مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ یہ بات صرف زید سے تعلق رکھتی ہے بلکہ جو شخص بھی زہر کھائے گا مرجائے گا.پس گو اس فقرہ کا پہلا مخاطب زید ہوگا اور ہماری نصیحت صرف زید کو ہوگی کہ تو زہر نہ کھا.مگر اس سے یہ قاعدہ کلیہ بھی نکل آئے گا کہ جو شخص زہر کھائے گا مرجائے گا.میرے نزدیک ان آیات میں مقابر کے لفظ سے مٹی والی قبریں مراد نہیں بلکہ تباہی اور بربادی مراد ہے اور اگر ہم یہ معنے کریں تو یہ آیات اپنے مطالب کے لحاظ سے وسیع بھی ہوجاتی ہیں اور کسی غیر معمولی تاویل کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ.تم لوگوں کو تکاثر نے اتنا غافل بنادیا ہے کہ جن چیزوں سے تکاثر نے تمہیں روکا تھا ان کی طرف تم لوٹ نہیں سکے یہاں تک کہ تم تباہی کے سرے پر پہنچ گئے اور تمہاری بربادی کا وقت آگیا.پس زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ سے مقبرئہ جسمانی مراد نہیں بلکہ یہ وہ مقبرہ ہے جس کامحاورئہ زبان میںذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم تومرگئی یا فلاں شخص کے متعلق تم کیا پوچھتے ہو وہ تو مرگیا یعنی اس کے اندر بیداری کی روح
Page 202
نہیں رہی، اس میں اخلاقی زندگی نہیں رہی، اس میںدینی زندگی نہیں رہی، اس میں قومی زندگی نہیں رہی، اس میںسیاسی زندگی نہیں رہی، اس میں عائلی زندگی نہیں رہی.جب کسی قوم یا فرد کی یہ حالت ہو تو کہتے ہیں اس پر موت طاری ہوگئی.پس یہاں ان ساری چیزوں کی نفی کی گئی ہے جن سے تکاثر انسان کو محروم کردیا کرتا ہے اور کہا گیا ہے کہ تم میں دین بھی نہیں رہا، تم میں دنیا بھی نہیں رہی، تم میں اخلاق بھی نہیں رہے، تم میں علم بھی نہیں رہا.ایسا آدمی کسی ایک موت کے نیچے نہیں ہزاروں موتوں کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے.پس اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ کے معنے یہ ہوں گے کہ قومی طور پر تم پر تنزّل اور بربادی کا وہ دور آگیا ہے کہ جس کے بعد کوئی قوم زندہ نہیں کہلاسکتی.اور گو اس میں مکہ والے مخاطب ہیں مگر اس ذریعہ سے یہ قانون بھی بیان کردیا گیا ہے کہ جو قوم تکاثر کے پیچھے پڑ تی ہے وہ مقبرہ کو پہنچ جاتی ہے یعنی وہ قوم آخر مرجاتی اور دنیا سے ہمیشہ کے لئے نابود ہوجاتی ہے.غرض اس سورۃ میں مکہ والوں کی توجہ کو اس سبب کی طرف پھرایا گیاہے جو اقوام کو خدا تعالیٰ اور اس کے پیغام سے غافل کرکے آخر تباہ کردیتا ہے.چنانچہ دیکھ لو مکہ والوں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کے ذریعہ ایک بہت بڑی عزت حاصل ہوئی.ایک زمانہ میں دو رسول ان کی طرف مبعوث ہوئے جنہوںنے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے کانوں تک پہنچایا.اس کے نتیجہ میں ان میں بیداری بھی پیدا ہوئی اور ان میں زندگی کی روح بھی حرکت کرنے لگی.مکہ ایک بنجر اور غیر آباد علاقہ تھا.عاد اور ثمود کی قومیں اس علاقہ پر مدتوں سے حکومت کرتی چلی آئی تھیںمگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لانے کے نتیجہ میں ان کے اندر ایسا تغیر پیدا ہوا کہ حکومت ان کے قبضہ میں آگئی اور تمام عرب نے ان کے سامنے اپنی گردنیںخم کر دیں.اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں جب کسی قوم کو روحانی رنگ میں عزت ملتی ہے تو خدا تعالیٰ کے نبی اور اس کے مامور کی بعثت کے نتیجہ میں ہی ملتی ہے مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیوی عزت بھی اس قوم کو حاصل ہو جاتی ہے اور لوگ ان کی ظاہری عظمت کو دیکھ کر واہ وا کرنے لگتے ہیں.حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے نبی تھے بڑے صناع یا تاجر نہ تھے وہ اپنی قوم کو خدا دینے کے لئے آئے تھے صنعت یا تجارت یا حکومت میں غلبہ دینے کے لئے نہیں آئے تھے.مگر دین کے نتیجہ میں دنیوی حکومت بھی اس قوم میں آگئی اور اس کو صرف خدا نہیں ملا بلکہ بادشاہت اور حکومت بھی مل گئی.پس خدا تعالیٰ کی یہ سنت کہ جب کسی قوم کو ایک نبی کے ذریعہ خدا ملتا ہے تو اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے.اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قرب سے انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں اور اخلاق درست ہونے سے دنیا کی گردنیں بھی خود بخود جھکنے لگتی ہیں.آج تک کوئی نبی بھی دنیا میں ایسا نہیں آیاجس نے ایک ذلیل اور مقہور قوم کو اٹھاکر بلند ترین مقام تک نہ پہنچادیا ہو.موسوی قوم کیا تھی؟ پتھیروں کا کام کرتی تھی مگر موسٰی سے مل کر وہ بادشاہ بن گئے.
Page 203
عیسٰیؑ کے ماننے والے کیا تھے ؟چند مچھلیاں پکڑنے والے معمولی افراد تھے مگر عیسٰیؑ کو مان کر دنیا کے بادشاہ بن گئے.محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ماننے والے کیا تھے؟اونٹوں کے چرواہے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے وہ دنیا کے بادشاہ بن گئے.پس انبیاء صرف دین ہی نہیں لاتے بلکہ جوں جوں ان کی جماعت ترقی کرتی جاتی ہے ان کو دنیوی طور پر بھی غلبہ ملتاجاتاہے اور جب یہ غلبہ انہیں حا صل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جن پر ان کی نیکی اور تقویٰ اور روحانیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ ان کے ظاہری غلبہ کو دیکھ کر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے ان کو تو بہت بڑی شوکت حاصل ہوگئی ہے.غرض ایک مومن جماعت کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں.ایک اس کی ذاتی حیثیت ہوتی ہے اور ایک حیثیت وہ ہوتی ہے جس میں اسے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں.جب مومن اپنے نفوس پر ذاتی حیثیت سے غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمد للہ ہم لوگ خدا تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اس کی توحید کو تسلیم کرنے والے،اخلاق پر عمل پیرا ہونے والے اور اس کے اوامر کو پوری دیانت داری کے ساتھ بجا لانے والے ہیں.اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنا نبی ہم میں بھیجا اور پھر اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی اس کی غلا می میں بسر کریں.لیکن دوسرے لوگ اس حقیقت کو نہیں دیکھتے وہ صرف ان کی ظاہری عظمت کو دیکھ کر عش عش کر اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں کتنی بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے.جب ابوبکرؓ اور عمرؓ کو صحابہؓ دیکھتے تھے تو ابوبکرؓ بادشاہ یا عمرؓ بادشاہ کی حیثیت میں نہیں دیکھتے تھے بلکہ اس حیثیت میں دیکھتے تھے کہ ابو بکرؓ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور جسے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں کرنے کا موقع ملا.اسی طرح عمرؓ وہ ہے جس نے ا سلام کی بہت بڑی خدمات سر انجام دیں.وہ ان کی خوبی ان کی ظاہری شوکت میں نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی بڑی خوبی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نمازوں میں برکت رکھی ہے.ان کی دعائوں میں برکت رکھی ہے.ان کے روزوں میں برکت رکھی ہے.ان کے تقویٰ میں برکت رکھی ہے اور انہیں اپنے قرب کے لیے چن لیا ہے یہ تو وہ چیز تھی جو صحابہؓ کو نظر آتی تھی مگر عیسائیوں اور یہودیوں کو کیا نظر آتا تھا ؟ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ابوبکرؓ بڑا نمازی ہے یا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا اس نے اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بھاری قربانیاں کی ہیں وہ ان ساری باتوں سے اندھے تھے.انہیں اگر نظر آتا تھا تو یہ کہ ابوبکرؓ بڑا بادشاہ ہو گیا ہے.عمرؓ بڑا بادشاہ ہو گیا ہے انہوں نے قیصر کو شکست دے دی ہے، انہوں نے کسریٰ کو تباہ کر دیا ہے، انہوں نے ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے.پس جب نبی کے ذریعہ کسی جماعت کو حکومت ملتی ہے تو اس کے بعد
Page 204
اس کے کان میں یہ ایک نئی آوازآنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے ہو گئے ہیں.دنیوی ترقی سے پہلے تو یہ آوازیں آیا کرتی تھیں کہ یہ لوگ نماز یں پڑھنے والے،روزے رکھنے والے، دعائیں کرنے والے،صدقہ وخیرات میں حصہ لینے والے،غرباء اوریتامیٰ و مساکین کا خیال رکھنے والے ہیں.لیکن جب انہیں غیر قوموں پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے دولت مند ہیں،بڑے با اثر ہیں،بڑی رعایا ان کے ماتحت ہے،ان کا مقابلہ ہم کہاں کر سکتے ہیں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب زمانہ نبوت سے بُعد ہو جاتا ہے اور وہ لوگ مر جاتے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت میں اپنا وقت گذارا ہوتا ہے اور جو جانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں تھے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا اور جو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا تو ان کی اولادیں نفس کی آواز کی نسبت دوسرے لوگوں کی آوازوں پرزیادہ کان دھرنا شروع کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اب دوسروں کا فرض ہے کہ ہماری غلامی اختیار کریں.چنانچہ دیکھ لو ایک عرصہ کے بعدصحابہ ؓ کو بڑی عظمت حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومتیںبھی دے دیں مگر چونکہ وہ اپنے نفس میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اونٹوں کے چرواہے تھے اس لیے ان میں حکومت کے زمانہ میں بھی کبر پیدا نہیں ہوا.جب کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے تو مال غنیمت میں کسریٰ کا وہ رومال بھی آیا جو وہ اس وقت اپنے ہاتھ میں لیا کرتا تھا جب وہ تخت پر بیٹھتا تھا.کسریٰ کو اس رومال کی عظمت کا کوئی احساس ہوگا لیکن صحابہؓ اس کی کیا عظمت سمجھتے تھے.ان کے نزدیک تو ساری عظمت نماز میں تھی، روزہ میں تھی، حج میں تھی، زکوٰۃ میں تھی،صدقہ و خیرات میں تھی، غریبوں کو کھانا کھلانے میں تھی،تعلیم میں تھی، تربیت میں تھی.میرا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دلوں میں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں تھی بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے مقابلہ میں جو اس نے ان پر اس رنگ میں کیا کہ انہیں محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نصیب ہوا ان چیزوں کو بالکل حقیر سمجھتے تھے.جس طرح آج کل کے بعض فیشن ایبل نوجوان اپنی جیب میں رومال ذرا باہر نکال کر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی نظر آتا رہے اسی طرح کسریٰ یہ رومال تخت پر بیٹھتے وقت اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا.یہ رومال مال غنیمت میں تقسیم ہو کر حضرت ابوہریرہؓ کے حصہ میں آیا.ایک دن انہیں کھانسی اٹھی اور بلغم آیا تو انہوں نے وہ رومال نکال کر اس میںتھوک دیا اور پھر کچھ خیال آنے پر کہا بَـخِّ بَـخِّ اَبُوْہُرَیْرَۃَ.واہ وا ابوہریرہ تیری بھی کیا شان ہے کبھی بھوک کی وجہ سے تجھے جوتیاں پڑا کرتی تھیں اور آج تو کسریٰ کے رومال میں تھوک رہا ہے.لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوہریرہؓ نے کہا میں نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ایک لمبا عرصہ گذر چکا تھا چنانچہ میرے ایمان لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تین سال
Page 205
زندہ رہے چونکہ میں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا تھا اس لیے میں نے عہد کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ سے اب ہلوں گا نہیں.لوگوں نے تو بہت باتیں سن لی ہیں مگر میں نے کچھ نہیں سنا.معلوم نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زندگی باقی ہے اس لیے اب میں آپ کے دروازہ پر پڑا رہوں گا تا ہر بات آپؐکی سنوں اور اسے یاد رکھوں.چنانچہ میں مسجد میں ہی بیٹھا رہتا اور اس ڈر کے مارے کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لے آئیںاور آپ کی باتیں سننے سے محروم نہ رہوں ادھر ادھر بھی نہ جاتا اور نہ کوئی کمائی کرتا.میں یہی سمجھتا تھا کہ اگر میں نے کوئی روزگار کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پھر پرانے لوگ ہی سن لیں گے اور میں ان کے سننے سے محروم رہوں گا.چنانچہ میں مسجد میں ہی بیٹھا رہتا.بعض لوگ مجھے روٹی دے جاتے اور میں خدا تعا لیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے کھا لیتا.لیکن بعض دفعہ مجھے سات سات وقت کا فاقہ ہو جاتا اور کوئی شخص میرے لیے روٹی نہ لاتا آخر اس قدر ضعف ہو جاتا کہ میں بے ہوش ہو کر گر جاتا اور لوگ سمجھتے کہ مجھے مرگی کا دورہ ہو گیا ہے.عربوں میں اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ جب کسی کو مرگی کا دورہ ہوتا تو اس کے سر پرجوتیاں مارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اس کا علاج ہے.ابو ہر یرہؓ کہتے ہیں جب میں بے ہوش ہوتا تو لوگ اسی معمول کے مطابق میرے سر پر بھی جوتیاں مارنے لگ جاتے اور وہ سمجھتے کہ مجھے مرگی کا دورہ ہو گیا ہے حالانکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا.اب کجا تو یہ حالت تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوجاتا تو لوگ میرے سر پر مرگی کا دورہ سمجھ کر جوتیاں مارتے اور کجا یہ حالت ہے کہ کسریٰ کا وہ رومال جس کا میلا ہونا بھی کسریٰ برداشت نہیں کر سکتا تھا میں اس میں بلغم تھوک رہا ہوں.غرض صحابہؓ کے سامنے ہمیشہ اپنے ابتدائی حالات رہتے تھے.وہ جانتے تھے کہ ہماری پہلے کیا حالت تھی اور ہم نے کس طرح ترقی کی.وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ترقی محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نصرت کا نتیجہ ہے ہماری کسی ذ اتی خوبی کا اس میں دخل نہیں یا اگر ہمیں یہ چیزیں ملی ہیںتو اس لیے نہیںکہ یہ چیزیں بڑی تھیں بلکہ اصل چیز تو تقویٰ وطہارت ہے یہ چیزیں محض بطور انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہیں.مگر جب ان کی اولادیں پیدا ہوئیں.جب وہ لوگ آئے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا تھا.جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری کا مشاہدہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارا خدا پر بھی حق ہے، ملائکہ پر بھی حق ہے،سلسلہ پر بھی حق ہے، لوگوں پر بھی حق ہے اور سب کا فرض ہے کہ ہمارے لیے آرام و آسائش کے سامان مہیا کریں.اتنے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی آوازیں بھی ان کے کانوں میں آنی شروع ہو گئیں کہ یہ لوگ بڑے دولت مند ہیں.نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تکاثر میں مبتلاہو گئے اور خدا تعالیٰ کے انعامات کو بھول گئے.ہر نبی کے بعد ایسا ہواہے.موسٰی آئے
Page 206
تو ان کے بعد ایسا ہی ہوا.عیسٰیؑ آئے تو ان کے بعد ایسا ہی ہوا.محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے بعد بھی ایسا ہی ہواگو خدا تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں میں تقویٰ کا زمانہ بہت لمبا رہا ہے اور کم لوگ ایسے گذرے ہیں جنہوں نے تکاثر سے کام لیا.بہر حال جب ایسازمانہ آتا ہے کہ انبیاء کی جما عتوں کی دنیوی عزت دیکھ کر لوگ واہ وا کہنے لگ جاتے ہیں تو تکا ثر کا راستہ کھل جاتا ہے اور وہ اس واہ وا کے اثر کے نیچے اسی راستہ پر چلنے لگتے ہیں جس راستہ پر پہلی قومیں چلیں اور جو اصل چیز ہوتی ہے اسے بھول جاتے ہیں اور جب دین کو بھول جاتے ہیںتو خالص مقصود دنیا رہ جاتی ہے اور وہ بے تحاشہ اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیںآخر اس کے تین نتائج پیدا ہوتے ہیں.دنیا طلبی کے تین نتائج اوّل.بنی نوع انسان میں ان کے خلاف ردعمل پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تکاثر کے نتیجہ میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر کے نتیجہ میں لوٹ مار اور ظلم پیدا ہوتا ہے آخر بنی نوع انسان میں ان کے خلاف جوش پیدا ہوتا ہے اور وہ حکومت کو تباہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.دوم.کبھی بنی نوع انسان میں تو ان کے خلاف رد عمل پیدا نہیں ہوتا لیکن ان کی اپنی اولاد ان کی کمائی کواستعمال کر کے عیاش ہو جاتی ہے اور اس طرح ان میں اندرونی زوال پیدا ہونے لگتا ہے.باپ دادا کی جائیداد چونکہ مفت ہاتھ میں آجاتی ہے اس لیے عیاشی میں مبتلا ہو کر وہ سب کچھ برباد کر دیتے ہیں.بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں مگر عیاشی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انہوں نے کنچنیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں.شرابیں پیتے رہتے ہیں اور حکومت کے کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برباد ہوجاتے ہیں اور ان کی حکومت امراء میں تقسیم ہو جاتی ہے.سوم.یا پھر اللہ تعالیٰ سے ہی اس قوم کی ٹکر ہو جاتی ہے یعنی کوئی ایسا سبب پیدا ہو جا تا ہے کہ دنیوی تباہی کے سامان تو نہیں ہوتے لیکن خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر اس قوم کو با لکل تباہ کر دیتا ہے.غرض جب کوئی قوم تکاثر کے نتیجہ میں زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کے مقام پر پہنچ جائے تو اس میں ان تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور پیدا ہو جاتی ہے.یا تو رعایا میں رد عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے حاکموں کو توڑ دیتے ہیں یا اندرونی طور پر حکام میں ایسا تنزّل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اور یا پھر خدائی غضب نازل ہو کر ان کو تباہ کر دیتا ہے.مسلمانوں کے مقابل پر کفار مکہ کی حالت چونکہ گذشتہ کئی سورتوں سے اہل مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جا رہاہے کہ تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کھڑاہونا اپنے آپ کو
Page 207
ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گرانا ہے.تم لاکھ کوشش کرو اس مقابلہ میں تمہیں کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی.اس لیے ظاہر ہے کہ اس سورۃ میں بھی اہل مکہ سے ہی خطاب کیا گیا ہے.پہلی سورتوں میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، مساکین کو دھکے دیتے ہو،یتامیٰ کی کبھی خبرگیری نہیں کرتے، مال ودولت آئے تو سب عیاشی میں اڑادیتے ہو اور اگر کوئی شخص روپیہ کو عیاشی میں نہیں اڑاتا تو وہ اتنے بخل سے کام لیتا ہے کہ قومی ضرورتوں کے باوجود وہ اس روپیہ کو غلق میں بند کرکے بیٹھ رہتا ہے اور اسے کسی مفید مصرف میں نہیں لاتا.اسی طرح بتایا گیا تھا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم غلاموں کو مارتے ہو.عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے اور ہر قسم کے ظلم وستم سے کام لیتے رہتے ہو.اس کے مقابلہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ وہ ہیں جن میں نیکی اور تقویٰ بدرجہ کمال پایاجاتا ہے.وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں،وہ مساکین پر رحم وشفقت سے کام لیتے ہیں، وہ یتامیٰ کی خبر گیری کرتے ہیں، وہ مال ودولت کی حفاظت کرتے ہیں،وہ قومی ضرورتوں کو اپنی ذاتی ضروریا ت پر مقدم رکھتے ہیں.اسی طرح وہ غلاموں سے حسن سلوک کرتے ہیں،وہ عورتوں کو ان کے حقوق پوری دیانتداری کے ساتھ اداکرتے ہیںاور کبھی ظلم وستم کے قریب بھی نہیں جاتے جب تمہاری حالت اور ان کی حالت میں اس قدر بیّن فرق ہے تو تم کس طرح یہ خیال کر سکتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی.اب فر ماتا ہے اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ.تم کو ہوشیار ہوجانا چاہیے اور تمہیں اپنے دل کے اندرونی گوشوں سے یہ خیال با لکل نکال دینا چاہیے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکو گے.کیا تم اپنے نفس پر غور نہیں کرتے کہ تم گرتے گرتے کس مقام پر جا پہنچے ہو.دنیا کی محبت تم میں ہے، مال کی محبت تم میں ہے،عزت کی محبت تم میں ہے اور تم نے زندہ رہنے کا مادہ با لکل مٹا ڈالا ہے.زندہ رہنے کے دو ہی مادے ہوتے ہیں یا دین ہوتا ہے یادنیا ہوتی ہے.تکاثر والا دین کو بھی بھول جاتا ہے اور دنیوی لحاظ سے بھی ذلت ورسوائی کے گڑھے میں جا پڑتا ہے.دین کو تو وہ اس طرح بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات دونوں اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور دنیا میں وہ اس طرح ذلیل ہوتا ہے کہ تکاثر کے نتیجہ میں تکبر اور خودپسندی میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق کو فراموش کر دیتا اور ان پر مختلف رنگ کے مظالم شروع کر دیتا ہے.غرض دو ہی چیزیں ہیں جو کسی قوم کو زندہ رکھ سکتی ہیںیا تو دینی روح کسی قوم کو زندہ رکھا کرتی ہے اور یا پھر دنیوی روح کسی قوم کے عروج کا باعث ہوا کرتی ہے مگر تکاثر ان دونوں کو مٹا دیتا ہے.پس فرماتا ہے جب تمہارے اندر تنزّل کے آثار پوری طرح پیدا ہوچکے ہیںتو کیا اب بھی تم سمجھتے ہو کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کچل دو گے اور جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں
Page 208
اس میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دو گے.موت تمہارے سر پر کھڑی ہے اور تمہاری اپنی جان نکل رہی ہے مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بجائے اپنے حالات پر غور کرنے کے اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی تباہی کے خواب دیکھ رہے ہو یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے بعض دفعہ کوئی امیر شخص مر رہا ہوتا ہے.موت دروازہ پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور ہر شخص کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ چند گھڑیوں کا مہمان ہے مگر اس وقت جب اس کے کسی نوکر سے دوائی گر جاتی ہے تو وہ انتہائی غصہ سے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی تم نے دوائی گرا دی ہے اگر تم نے پھر ایسی حرکت کی تو میں تمہاری خوب خبر لوں گا.حالانکہ دو منٹ کے بعد وہ خود مر جاتا ہے یہی حالت اس وقت تمہاری ہے کہ تکاثر کی عادت میں بڑھتے بڑھتے تم ایسے مقام پر پہنچ چکے ہو کہ تم قبروں میں پائوں لٹکائے بیٹھے ہو اور تمہاری تباہی اور بربادی با لکل یقینی ہے جیسے قبر میں سے کوئی مردہ نکل کر واپس نہیں آسکتا اسی طرح تم اس قدر ذلیل اور رسوا ہو چکے ہو اور اس قدر دینی اور دنیوی موتیں تم پر وارد ہو چکی ہیں کہ تم اب اپنی اس حالت سے لوٹ ہی نہیں سکتے.پس اب تمہارا یہ کہنا کہ ہم جیت جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہار جائیں گے اگر پاگل پن کی بات نہیں تو اور کیا ہے.مردہ اسی وقت زندہ ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں نئی روح داخل کی جائے.اگر نئی روح اس میں نہ پھونکی جائے تو کوئی مردہ جسم دوبارہ زندگی حاصل نہیں کر سکتا.یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے اور وہ یہ کہ یہ سورۃ تو اہل مکہ کی نسبت ہے اور ان کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں تھا پھر وہ تکاثر کے مجرم کس طرح ہو گئے.اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قوم کی دولت نسبتی ہوتی ہے اگر ان کے مالدار چھوٹے تھے تو ان کے غریب بھی تو بہت غریب تھے پس تکاثر نسبتی امر ہے.کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کروڑوں نہیں اس لئے میں تکا ثر کا مجرم نہیں.امریکہ والوں کے لئے تکاثر کے اور معنے ہیں.انگلستان کے لئے اور.اور ہندوستان کے لئے اور.اس میں سے ہندوئوں کے لئے اور.مسلمانوں کے لئے اور.پھر احمدیوں کے لئے اور.جس قوم پر جو ذمہ داری ہے چھوٹی ہو یا بڑی،اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے سے قاصر ہے تو تکاثر کی مرتکب ہے بلکہ جب بھی دین یا دنیا کے کسی اچھے کام کے لئے کسی قربانی کی ضرورت ہے اور کوئی شخص اس وقت اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے گو اس کے پاس ایک ٹکڑا روٹی کا ہی تھا وہ تکاثر کا مرتکب ہے کیونکہ اس نے ایک چیز اپنے پاس رکھ لینی چاہی جو دوسروں نے قربان کر دی تھی یا جس کی اس کے دین یا اسی قوم کو ضرورت تھی.جس قوم میں یہ نقص پیدا ہو جائے اور قربانی میں دریغ کرنے لگے وہ تباہ ہو جاتی ہے.اسی لئے فرمایا حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ یعنی یہ مرض آخر قومی موت کی طرف لے جاتا ہے.
Page 209
اس جگہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تکاثر اور تفاخر کلی طور پر ممنوع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ اس تکاثر کا ذکر ہے جو انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے.جیسا کہ فرماتا ہے اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ.حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ اس تکاثر نے تم کو تمام نیک باتوں سے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم موت تک پہنچ چکے ہو.یعنی اگر نیک باتوں پر فخر ہو یا ایسی باتوں پرفخر ہو جو دوسروں کو نیکی اور تقویٰ کی طرف لانے میں ممد ہوں تو اس قسم کا تفاخر منع نہیں.گویا تفاخر کی دو قسمیں ہیں ایک تفاخر وہ ہے جو انسان کو مقابر کی طرف لے جاتا ہے اور ایک تفاخر وہ ہے جو انسان میں زندگی پیدا کرتا ہے.جو تفاخر انسان کو مقابر کی طرف لے جاتا ہے وہ کلی طور پر ممنوع ہے اور جو تفاخر زندگی پیدا کرتا ہے وہ منع نہیں.چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا اَنَا سَیِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَا فَـخْرَ (سنن ابن ماجہ کتاب الزھد باب ذکر الشفاعۃ) مجھے خدا تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کا سردار بنایا ہے مگر اس کے باوجود میں اس پر فخر نہیں کرتا.یہ نہیں کہ میں تم کو ذلیل سمجھوں اور اپنے آپ کو تم سے کوئی علیحدہ ہستی قرار دوں میرا فرض ہے کہ میں سید ولد آدم ہونے کے باوجود تمہاری خدمت کروں اور تمہیں ترقی کے میدان میں بہت آگے لے جائوں اسی طرح فرماتے ہیں تَزَوَّجُوْا وَلُوْدًا وَدُوْدًا فَاَنَا مُکَاثِرُبِکُمُ الْاُمَمَ وَ مُفَاخِرُ بِکُمْ ( سنن ابی داؤد کتاب النکاح باب النـھی عن تزویج من لم یلد من النساء ) تم شادیاں کرو جننے والی اور محبت کرنے والی عورتوں سے کیونکہ تمہارے ذریعہ سے میں دوسری قوموں پر فخر کرنے والا ہوں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کثرت تعداد کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ پسندیدہ قرار دیتا ہے مگر چونکہ بعض کثرتیں نہایت گندی ہوتی ہیں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف یہ خواہش نہیں رکھتا کہ تم اپنی تعداد کے لحاظ سے دوسری قوموں سے بڑھ جائو بلکہ میری خواہش یہ بھی ہے کہ باوجود کثیر ہونے کے تم ایسے نیک اور پاک بنو کہ میں قیامت کے روز دوسری امتوں کے مقابلہ میں تم پر فخر کر سکوں.اس حدیث میں وُلُوْد کا لفظ کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وُدُوْد میں تفاخر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض کثرت پر نہیں بلکہ اپنی امت کے اعلیٰ اخلاق پر فخر کریں گے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کریں اور کوشش کریں کہ ان کی نیکی صرف ان کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ اس کا اثر نسلاً بعد نسلٍ ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوتا چلا جائے تو وہ ایسی اعلیٰ درجہ کی نسلیںپیدا کر سکتے ہیں جو اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعث فخر ہوں.افسوس کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں.ان میں ذاتی طور پر تقویٰ بھی ہوتا ہے، روحانیت بھی ہوتی ہے، اعلیٰ اخلاق بھی ہوتے ہیں، رأفت اور شفقت کے جذبات بھی ہوتے ہیں، حلم بھی موجود ہوتا ہے، حصول علم کی بھی
Page 210
پیاس ہوتی ہے، نیکیوں میںبڑھنے کا مادہ بھی ہوتا ہے مگر اس بات کی طرف انہیں کبھی توجہ پیدا نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد میں بھی وہ یہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کریں.بے شک ورثہ کے ذریعہ بھی ماں باپ کے بعض خصائص اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں مگر اعلیٰ نسل کا بہت بڑا تعلق اعلیٰ تربیت سے ہوتا ہے اور مومن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس پہلو میں کبھی غفلت سے کام نہ لے.اگر ہر شخص خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنی اولاد کی نیک تربیت میں مشغول ہو جائے اور کوشش کرے کہ اس کی اولاد اس سے بڑھ کر اسلام کی فدائی ثابت ہو تو مسلمانوں میں کبھی تنزّل پیدا نہ ہو.بڑی وجہ قومی انحطاط کی یہی ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کی جاتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثرت محض بے کار بن کر رہ جاتی ہے اور قوم کا رعب بالکل مٹ جاتا ہے.پس اصل چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں نیکی اور تقویٰ کے میدان میں ہم سے بھی تیز تر ہوں کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرسکتے ہیں.محض کثرت ایسی چیز نہیں جو کسی کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہو.حضرت علیؓ کا قول ہے کہ اَنَا قَطَعْتُ خُرْطُوْمَ الْکُفْرِ بِسَیْفِیْ فَصَارَ الْکُفْرُ مُثْلَۃً ( روح البیان زیر سورۃ التکاثر) یعنی میں وہ شخص ہوں جس نے تلوار کے ذریعہ کفر کا ناک کاٹ دیا ہے.چنانچہ اب وہ نکٹا ہو گیا ہے.مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خدمت اسلام کی ایسی اعلیٰ درجہ کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ کفر و شرک سے تعلق رکھنے والے تمام اہم امور کا میرے ہاتھوں سے قلع قمع ہو چکا ہے.اب اس میں طاقت نہیں کہ میرے مقابلہ میں اپنا سر اٹھا سکے مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ حضرت علیؓ میں تکبر پیدا ہو گیا تھا یا آپ اپنی خدمات کی وجہ سے دوسروں کو اپنے مقابلہ میں حقیر سمجھنے لگ گئے تھے بلکہ مطلب یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس اہم کام کو سر انجام دینے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے میری خواہش ہے کہ تم بھی وہی کام کرو اور اسی راستہ پر چلو جس پر میں چلا ہوں.پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ( البقرۃ:۱۴۹) اے مومنو! تم نیکیوں میںبڑھنے کی کوشش کرو.استباق کے معنے صرف خود بڑھنے کے نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کے ہوتے ہیں.پس اس حکم کا صرف اتنا مفہوم نہیں کہ تمہیں ذاتی طور پر نیکیوں میں ترقی کرنی چاہیے بلکہ اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس دوڑ میں شامل کرنا چاہیے اور شانہ بشانہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے.اگر کسی قوم میں استباق کی روح پیدا ہو جائے تو وہ اپنی ترقی کی منازل سالوں اور مہینوں کی بجائے دنوں اور گھنٹوں میں طے کر سکتی ہے مثلاً اگر کسی شخص نے قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھ لیا ہے تو وہ اس حکم کے مطابق کوشش کرے گا کہ دوسروں کو بھی وہ پارہ پڑھا دے اور اگر کسی نے ترجمہ
Page 211
پڑھ لیا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ دوسروں کو بھی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا دے اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کے معارف سے آگاہ ہو گیا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں دوسروں کو بھی قرآن کریم کے معارف سے آگاہ کر دوں غرض استباق کی روح اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ آن کی آن میں کہیں کی کہیں جا پہنچتی ہے.اسی طرح فرماتا ہے وَ مِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ ( فاطر:۳۳) مومنوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں.پھر فرماتا ہے فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا( النّٰـزِعٰت:۵) مومنوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہوئے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں.درحقیقت یہ علامت ان اقوام کی ہے جو اپنے اندر زندگی کی روح رکھتی ہیں.وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ دوسروں سے آگے نکل جائیںاور نیکی کے میدان میں کسی کو سبقت نہ لے جانے دیں.اسی طرح فرماتا ہے سَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ( اٰل عـمران :۱۳۴) اے لوگو! تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے جلد پہنچنے کی کوشش کرو یعنی تیزی کے ساتھ اپنے قدم بڑھائو اور خدا تعالیٰ کی مغفرت کو جلد سے جلد حاصل کرنے کی کوشش کرو.یہ امر ظاہر ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی مغفرت کی طرف سر عت سے اپنے قدم بڑھائیں گے ان میں سے کوئی آگے نکل جائے گا اور کوئی پیچھے رہ جائے گا کسی شخص کو اس بات پر فخر ہوگا کہ میں نے دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مقام حاصل کر لیا اور کوئی حسرت وافسوس کے ساتھ آہ بھرے گا کہ میں نے وقت ضائع کر دیا اور خدا تعالیٰ کی مغفرت کو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے حاصل نہ کر سکا.بہر حال یہ آیات بتاتی ہیںکہ بعض قسم کے تفاخر اسلام میں ممنوع نہیں.وہ تکا ثرجو انسان کو بنی نوع انسان کی خدمت میں مشغول کر دے جس تکاثر کے نتیجہ میں انسان کی روحانیت اور اس کا تقویٰ بڑھ جائے،جس تفاخر کے نتیجہ میں قوم کا معیار بلند ہو جائے وہ برا نہیں بلکہ اچھا ہے اور ہر سمجھدار انسان کا فرض ہے کہ وہ اس تکا ثر میں حصہ لے کیونکہ بغیر اس کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی.اگر کسی لڑکے کو کالج میں بھیجا جائے اور وہ کہے کہ میں کالج میں نہیں جاتا کیونکہ میرے دوسرے ساتھی بھی نہیں جاتے.اگر میں کالج میں گیا اور وہا ں میں نے تعلیم حاصل کی تو میں دوسروں سے بڑھ جائوں گا تو یہ اس کی حماقت کا ثبوت ہوگا کیونکہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعداس کا دوسروں سے بڑھنا قوم کے لئے مفید ہوگا مضرنہیں ہوگا.اگر وہ پڑھ کر آئے گا تو دوسروں کو بھی پڑھائے گا اور اس طرح قوم کا تعلیمی معیار اونچا ہوجائے گا.پس تکاثر اور تفاخرکی ہر صورت ممنوع نہیں بلکہ صرف وہ تفاخر ممنوع ہے جو انسان کو مقابر کی طرف لے جاتاہے اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ کے بعد زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کہا کیونکہ جسمانی موت تو خود آتی ہے لیکن یہ دینی یا اخلاقی یا قومی ہلاکت انسان خود بلاتا ہے اور اپنے قدموں چلتا ہوا اپنی قبر میں جا لیٹتاہے.اگر
Page 212
حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کی جگہ حتّٰی مُتُّمْ فرماتا تو یہ مضمون ادا نہ ہو سکتا.حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مضمون میں ایک خاص شان اور جدت پیدا کرتے ہوئے بنی نوع انسان کو اس نہایت اہم نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قومی تباہی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ناجائز تکا ثر سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ تمام نیک اخلاق جو انسان کی قومی اور مذہبی زندگی کا اصل باعث ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں.نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس روح مفاخرت کی وجہ سے قوم اپنے مقام سے گرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے جب موت اس پر پوری طرح سوار ہو جاتی ہے اور ترقی کی دوڑ میں ایک بے جان جسم سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی.كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَۙ۰۰۴ ( خوب یاد رکھوکہ تمہاری حالت) اس طرح نہیں (جس طرح تم سمجھتے ہو بلکہ)تم لوگ (قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت کو) جلد ہی جان لو گے ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَؕ۰۰۵ پھر (ہم کہتے ہیں کہ تمہاری حالت)یوں نہیں(جس طرح تم سمجھتے ہو )تم عنقریب ہی(اس بات کو ) جان لو گے.تفسیر.كَلَّا ہمیشہ زجر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس جگہ بھی اہل مکہ کو خبر دار اور ہوشیار کرنے کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ خبردار تمہاری یہ حالت سخت خطرے والی ہے ہم نے جو کہا ہے کہ اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ.حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ.تمہیں تکاثر نے گراتے گراتے اس حالت تک پہنچادیا ہے کہ تم مقبرہ میں جا پہنچے ہو.ہماری اس بات کی سچائی کو ابھی تم سمجھے نہیں اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ محض ایک بڑ ہے.مگر یاد رکھو تھوڑے ہی دنوں تک تمہیں اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ ہماری بات با لکل سچی ہے اور زندگی کے آثار تم میں موجود نہیں رہے.دیکھو اگر یہاں مقابر سے ظاہری قبریں مراد ہوتیں تو كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ کے کیا کوئی بھی معنے ہو سکتے تھے.کیا ابو جہل، عتبہ اور شیبہ یہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے.جب وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ انسان فا نی ہے اور وہ تھوڑی سی عمر لے کر اس دنیا میں آیا ہے تو یہ کہنا کس قدر بے معنی ہو جاتا تھا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے ضرور مرنا ہے دیکھو ہم پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے ضرور مرنا ہے اس صورت
Page 213
میں تو یہ ایک ہنسی کے قابل بات بن جاتی ہے کہ جس بات کو ہر فرد تسلیم کرتا ہے اس کے متعلق کہا جارہا ہے کہ دیکھو تمہیں اس کا عنقریب پتہ لگ جائے گا.میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں اس کا عنقریب پتہ لگ جائے گا.یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس جگہ تباہی اورذلت ورسوائی والی قبر ہی مراد ہے اور یہی وہ قبریں تھیں جن کا کفار مکہ کو بڑی سختی سے انکار تھا.مٹی کی قبروں کو تو ابوجہل بھی تسلیم کرتا تھا مگر وہ اس بات کو ماننے کے لئے ہرگز تیار نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مَیں ہار جائوں گا.ورنہ جس بات کو کوئی دوسرا شخص مانتا ہو اس پر زور دینا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی دوسرے شخص سے کہے کہ میں کہتا ہوں تم آدمی ہو.میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم آدمی ہو.میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم آدمی ہو.ان فقرات کو جو شخص بھی سنے گا ہنس پڑے گا کہ کہنے والا پاگل ہو گیا ہے پس اگر اس جگہ مٹی کی قبریں ہی مراد ہوتیں تو كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ اس موت کو تو کفار مکہ میں سے ہر فرد تسلیم کرتا تھا اور جس بات کو ان کا ہر چھوٹا بڑا تسلیم کرتا تھا اس پر زور دینا با لکل بے معنی ہو جاتا ہے.حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ قومی تباہی اور بربادی کو ہی مقابر قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو کر سن لو تم ضرور جان لو گے کہ تم قبروں میں پہنچ چکے ہو.ہم پھر کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جائو تم کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم سچ کہتے ہیں كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ میں جو تکرا ر آیا ہے اس کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ یہ تکرار تاکید مضمون کے لیے آیا ہے (تفسیر الرازی سورۃ التکاثر زیر آیت كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص مواقع پر بات کو بار بار دہراتے تھے.اس صورت میں ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ میں یہ محذوف سمجھا جائے گا کہ ثُمَّ اَقُوْلُ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.حضرت علی ؓ کا قول ہے کہ اس جگہ تکرار محضہ نہیں بلکہ چونکہ واقعہ مقرر ہوگا اس لئے دو دفعہ بیان کیا ہے.ان کے نزدیک پہلا تَعْلَمُوْنَ قبر کے متعلق ہے اور دوسرا نشر کے متعلق.وہ فرماتے ہیں اَلْاَوَّلُ فِی الْقُبُوْرِ وَالثَّانِیْ فِی النُّشُوْرِ.(روح المعانی سورۃ التکاثر زیر آیت كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ) مگر میرے نزدیک اس جگہ یا تو تکرار توکید ہے یا پہلا جملہ دنیا کے متعلق ہے اور دوسرا آخرت کے متعلق.جیسے فرمایامَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى(بنی اسـرآءیل:۷۳)یعنی تمہیں دنیا میں بھی اپنی ان حرکات کا انجام معلوم ہوجائے گا اور آخرت میں بھی تم عذاب الٰہی میں مبتلا کئے جائو گے.
Page 214
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِؕ۰۰۶ (حقیقت تمہارے خیالات کے مطابق) ہرگز نہیں (ہے) کاش تم علم یقینی کے ساتھ (حقیقت کو ) جانتے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَۙ۰۰۷ (تو تم کو معلوم ہو جاتا کہ ) تم ضرور جہنم کو (اسی دنیا میں ) دیکھو گے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِۙ۰۰۸ (بلکہ ) پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے (آخرت میں ) بھی دیکھ لو گے.تفسیر.سابق مضمون کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں خبردار ہو جائو.کیوں تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ تم ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گر چکے ہو.یہ بات تو با لکل قطعی اور یقینی ہے کہ تم مر چکے ہو.زندگی کی کوئی علامت تم میں باقی نہیں رہی.موت کے سب سامان تمہارے لیے پیدا ہوچکے ہیں.خدا تعالیٰ کو تم بھلا چکے ہو بنی نوع انسان کے حقوق کو کلیۃً فراموش کر چکے ہو اور یہی دو چیزیں کسی قوم کی زندگی کی علامت ہوا کرتی ہیں.قوم زندہ ہوتی ہے اسی طرح کہ خدا اس قوم کے افراد کے دلوں میں زندہ ہوتا ہے جس قوم یا جس فرد کے دل میں اللہ تعالیٰ زندہ ہو وہ انسان زندہ کہلاتا ہے اور یا پھر بنی نوع انسان کی خدمت کا جذبہ کسی انسان کے دل میں ہو تو وہ انسان زندہ ہوتا ہے مگر تمہاری حالت تو یہ ہے کہ نہ تمہیں خدا تعالیٰ کی طاقتوں پر کوئی یقین ہے نہ بنی نوع انسان کی خدمت کا کوئی جذبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے کاش تمہیں علم الیقین ہی ہوتاتب بھی تم اس حقیقت کو بھانپ لیتے اور سمجھ لیتے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے یعنی جانے دو اس بات کو کہ ہم نے تمہاری ہلاکت کے متعلق پیشگوئی کی ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمیں اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں مگر دنیا میں ہر فعل کا ایک مادی نتیجہ بھی ہوتا ہے اور جب کوئی شخص کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے اس فعل کا کیا نتیجہ نکلے گا تو کیا تم اس نقطہ نگاہ سے اپنی حالت پر غور نہیں کرسکتے.لطیفہ مشہور ہے کہ شیخ چلی درخت پر چڑھا تو اسی شاخ کو کا ٹنے لگ گیا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا نیچے سے کوئی شخص گذرا تو اس نے شیخ چلی سے کہا کہ میاں تم یہ کیا کر رہے ہو کہ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو جس پر خود بیٹھے ہو تم تو گر جائو گے.
Page 215
شیخ چلی نے کہا تو کوئی عالم الغیب ہے تجھے کس طرح پتہ لگا کہ میں گر جائوں گا.جائو میں تمہاری بات نہیں مانتا.وہ چلا تو تھوڑی دیر کے بعد ہی شاخ کے کٹتے ہی شیخ چلی بھی نیچے آ گرا.یہ دیکھ کر وہ اس شخص کے پیچھے بھاگا اور کہنے لگا معلوم ہوتا ہے تو ولی ہے.کیونکہ جو بات تو نے کہی تھی وہ با لکل سچی نکلی اور میں گر پڑا.اس نے کہا میں ولی نہیں میں نے ایک طبعی نتیجہ نکالا تھا کہ چونکہ تم اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو جس پر خود بیٹھے ہو اس لئے تمہارا گرنا یقینی ہے.تو ہر فعل کا ایک طبعی نتیجہ ہوتا ہے جو بہر حال نکلتا ہے اور عقلمند انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا کیا اثر ہو گا.مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری عقلیں تو اتنی ماری ہوئی ہیں کہ تم ذرا بھی غور سے کام نہیں لیتے.اگر تم علمی طور پر ہی غور کرتے تو تمہیں یقین آجاتا کہ تم مر رہے ہو اور ہلاکت کے سامان تمہارے لیے چاروں طرف سے جمع ہیں.قومی ہلاکت کے ایک خدائی سامان ہوتے ہیں اور ایک دنیوی سامان ہوتے ہیں.خدائی سامان تو یہ ہوتے ہیں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کو نہ مانا، اس کے نبیوں کو نہ مانا،اس کے احکام کی خلاف ورزی کی.اور دنیوی سامان یہ ہوتے ہیں کہ قوم میں ظلم پایا جائے.غرباء و مساکین کی طرف اسے کوئی توجہ نہ ہو.عیاشی میں اس کے دن رات بسر ہونے لگیں.یہ دونوں سامان تمہارے لیے جمع ہیں.تم نے خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کر لیاہے اور بنی نوع انسان سے بھی تمہارا سلوک سخت ناقص ہے اور جب حالت یہ ہے تو تم کیونکر سمجھتے ہو کہ تم موت سے بچ سکو گے.پس فرماتا ہے كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ.لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو.جو کچھ میں کہتا ہوں اسے جھوٹ کہہ دو مگر کیا تم نے علمی رنگ میں بھی کبھی اپنے حا لات پر غور نہیں کیا کاش تمہیں علم الیقین ہی ہوتا تو تم سمجھتے کہ جس قوم میں تعلیم نہ ہو، جس قوم میں صدقہ وخیرات کی عادت نہ ہو،جس قوم میں انصاف نہ ہو، جس قوم میں انتظام نہ ہو،جس قوم میں رأفت نہ ہو اور رحمت نہ ہو وہ یقیناًہلاک ہو جاتی ہے اس میں کسی نبی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی.پس اگر تم میری باتوں کو تسلیم نہ کرتے صرف اپنے اندر علم الیقین پیدا کر لیتے تب بھی تم دیکھ سکتے تھے کہ جہنم تمہارے سامنے کھڑی ہے.تم دیکھتے کہ ہم قوم کو تعلیم نہیں دے رہے.تم دیکھتے کہ ہم قوم سے انصاف نہیں کر رہے تم دیکھتے کہ ہم اس کے حقوق کو نظر انداز کر رہے ہیں تم دیکھتے کہ ہم میں دیانت کی روح موجود نہیں، تم دیکھتے کہ ہم میں امانت کی روح موجود نہیں،تم دیکھتے کہ ہم میں تقویٰ کی روح موجود نہیں اگر تم دیکھتے کہ ہم میں عدل و انصاف کی روح موجود نہیں اسی طرح تم دیکھتے کہ ہم روپیہ کو صحیح طور پر خرچ نہیں کر رہے ہم اپنے باپ دادوں کی جائیدادوں کو عیاشی میں برباد کر رہے ہیں.اگر تم ان باتوں پر ذرا بھی غور کرتے تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ تم جہنم کو اپنے سامنے کھڑا پاتے یعنی تم میری باتوں کو بے شک جھوٹ سمجھ لو لیکن اگر تم اپنے حالات پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے تو تم دیکھ سکتے تھے کہ جہنم تمہارے سامنے موجود ہے.
Page 216
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ یہ قسم محذوف کا جواب ہے کیونکہ جحیم دیکھنا کفار کے علم یقین کے ساتھ لازم نہیں ہے لیکن یہ درست نہیں کیونکہ رویت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے.رویت عقلی، رویت عینی اور رویت مشاہدہ.علم الیقین کے بدلہ میں بھی ایک رویت حاصل ہوتی ہے جو رویت علمی ہوتی ہے.جب کسی شخص کو بہ دلائل کسی آنے والی مصیبت کا علم ہو جاتا ہے تو اس علم کے مطابق اس کے قلب کو اس مصیبت کے متعلق تکلیف بھی محسوس ہونے لگتی ہے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃوا لسلام نے یہی معنے مراد لیے ہیںاور فرمایا ہے کہ اس سورۃ میں علم کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں علم الیقین اور جو علم اس کے بعد آتا ہے یعنی عین الیقین.یقین کی ایک تیسری قسم بھی آپ نے بیان کی ہے یعنی حق الیقین جس کا ذکر سورۃالحاقہ میں ان الفاظ میں ہے کہ وَاِنَّہٗ لَحَقُّ الْیَقِیْنِ( الـحاقۃ:۵۲ ) پس اس جگہ رویت سے مراد رویت عقلی یا رویت علمی ہے.ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ کہہ کر فرمایا کہ یہ تو علمی بات تھی مگر میں پھر کہتا ہوں کہ تم ضرور دیکھ لو گے کہ موت تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے.ابھی تک تو تمہیں علمی رویت بھی حاصل نہیں لیکن تھوڑے دنوں تک تمہیں صرف علمی رویت ہی نہیں بلکہ عینی رویت بھی حاصل ہو جائے گی یعنی صرف دنیوی احساس ہی تباہی کے قریب پیدا نہ ہوگا بلکہ واقعہ میں پھر بلا نازل ہو جائے گی اور اسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کیونکہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ تم ضرور تباہ ہو جائو گے.یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ تم پہلے دنیا میں اپنی تباہی دیکھو گے اور پھر آخرت میں عذاب الیم کا شکار بنو گے.ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِؒ۰۰۹ پھر ( یہ بھی یاد رکھو کہ)تم سے اس دن (ہر بڑی ) نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا ( کہ تم نے اس کا شکر اداکیا یا نہ) تفسیر.نَعِیْم کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اس کے متعلق عربی سے ناواقف لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ جمع ہے.مجھے یاد ہے بچپن میں مَیںبھی اس غلطی میں مبتلا تھا.عام تراجم میں بھی غلطی سے نَعِیْم کے معنے نعمتوں کے ہی کئے جاتے ہیں مگر یہ درست نہیں.نَعِیْم کے معنے صرف نعمت کے ہیں نعمتوں کے نہیں.مگر اس لفظ کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ لوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں.
Page 217
اَلنَّعِیْم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اَلنَّعِیْم سے میرے نزدیک اس جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودمراد ہے اور اللہ تعا لیٰ فرماتا ہے کہ جب تم مر جائو گے تباہ اور برباد ہوجائو گے تو اس وقت میں تم سے پوچھوں گا کہ بتائو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت تھے یا نہیں ؟انہوںنے کب سے تمہیں ہوشیار کرنا شروع کیا تھا کہ بچ جائو ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں اپنے آپ کو مت گرائو.مگر تم نے ان کی نصیحت پر کان نہ دھرا اور آخر وہ وقت آگیا جب تم سچ مچ تباہ ہوگئے.تم غور کرو کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی مگر تم نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا.اس نے تمہیں وقت پر ہوشیار کر دیا تھا کہ دیکھو تم ایک خطر ناک گڑھے میں گر رہے ہو سنبھل جائو اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچالو.مگر تم پھر بھی نہ بچے اور اپنے آپ کو تباہ کر لیا.یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اَلنَّعِیْم سے ہر بڑی نعمت مراد ہو، اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کرکے اپنی تمام بڑی نعمتیں ان کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت بھی دی وہ نعمت بھی دی مگر تم نے میری ساری نعمتوں کو ضائع کر دیا.میں نے تمہیں روپیہ دیا تو تم نے اپنے گھروں میں رکھ لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ تم غریبوں پر خرچ کرو یا صدقہ و خیرات دو یا یتامیٰ و مساکین کی خبر گیری کرو.میں نے تمہیںحکومت دی تو تم نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا.میں نے تمہیں عزت دی تو تم نے لوگوں کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیا.غرض کون سی نعمت تھی جو میں نے تمہیں دی اور تم نے اس کا برا استعمال نہ کیا.پس اَلنَّعِیْم کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اَلنَّعِیْم سے نعمت کاملہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مراد ہو.اس صورت میں اس کا یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمت کاملہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے اس کی نصیحتوں سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا اور یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ اَلنَّعِیْم سے ہر بڑی نعمت مراد ہو یعنی مال ودولت، عزت ورسوخ اور حکومت جو خدا نے انہیں دی تھی اس کے متعلق ان سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ خدا تعالیٰ کے اتنے بڑے احسانات کے ہوتے ہوئے تم نے ان نعمتوں سے کیا فائدہ اٹھایا.یہ بھی انسان کے لیے سخت شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کہ جب کسی برے کام کا نتیجہ نکل آئے تو اسے یاد دلایا جائے کہ دیکھو فلاں وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہوشیار ہو جائو مگر تم ہوشیار نہ ہوئے.فلاں وقت میں نے تمہیں نصیحت کی تھی مگر تم اس سے متاثر نہ ہوئے.اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی کرے گا اور ان کو اپنی ہر بڑی نعمت یا نعمت کاملہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یاد دلائے گا اور کہے گا کہ بتائو کیا میرے اس قدر احسانات کے باوجود تمہارا یہی شیوہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اِباء و اِستکبار سے کام لیتے.میں نے خدا ہو کر چاہا کہ تم کو بچائوں مگر تم نے بندے
Page 218
ہو کر نہ چاہا کہ ہلاکت سے بچو.غرض اللہ تعالیٰ اپنی ہر بڑی نعمت انہیں گنائے گا اور انہیں شرمندہ اور ملزم کرنے کے لئے کہے گا کہ میری نعمتوں کی تم نے کچھ بھی قدر نہ کی.دنیا میں لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ کا نظارہ یہ تو آخرت کے لحاظ سے معنے ہیں.دنیا میں بھی تباہ شدہ اقوام پر لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ کا ایک وقت آیا کرتا ہے جب قومیں تباہ ہوتی ہیں اس وقت کفِ افسوس ملتی ہوئی ایک دوسرے سے کہا کرتی ہیں کہ ہمیں فلاں موقع ملا مگر ہم نے ضائع کر دیا.فلاں موقع ملا مگر ہم نے اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا کاش ہم سنبھل جاتیں اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے نہ کھودتیں.حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی خلافت کے ایام میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ میں تشریف لے گئے.جب حج سے فارغ ہوئے تو جیسے ہمارے ہاں عید کے موقعہ پر لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں اسی طرح بڑے بڑے رئووسا آپ کی خدمت میں مبارک باد دینے اور سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے.ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں حضرت عمر ؓ بیٹھے تھے بڑے بڑے ہال اس زمانہ میں نہیں ہوتے تھے کہ زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے گنجائش نکل سکے تھوڑے لوگ بھی آجاتے تو کمرہ بھر جاتا تھا.حضرت عمر ؓ اس خاندان میں سے تھے جو انساب کو یاد رکھا کرتا تھا اور جسے معلوم ہوتا تھا کہ فلاں شخص فلاں خاندان میں سے ہے اور فلاں شخص فلاں خاندان میں سے.اس وقت بڑے بڑے رئووسا جو کفار مکہ کی اولاد میں سے تھے آپ سے ملنے کے لئے آئے وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمرؓ چونکہ ہمارے خاندانوں کے حا لات سے خوب واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کتنی بڑی عزت رکھتے تھے اس لئے دوسروں کے مقابلہ میں وہ ہمیں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے.حضرت عمر ؓ نے بھی ان کو نہایت عزت سے بٹھایا.اپنے پاس جگہ دی اور مختلف امور پر ان سے باتیں شروع کر دیںابھی تھوڑی دیر ہی گذری تھی کہ ایک نو مسلم غلام آگیا حضرت عمر ؓ نے ان سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جائو اور انہیں بیٹھنے کے لئے جگہ دے دو.وہ پیچھے ہٹ گئے تو حضرت عمرؓ نے اس غلام کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے باتیں شروع کر دیںتھوڑی دیر گذری تو ایک اور نو مسلم غلام آگیا حضرت عمرؓ نے پھر فرمایا کہ ذرا پیچھے ہٹ جائو اور ان کو جگہ دے دو.وہ بیٹھا تو ایک تیسرانو مسلم غلام آیا پھر چوتھا پھر پانچواں یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے سات نو مسلم غلام آگئے اور حضرت عمرؓ ہر غلام صحابی کے آنے پر ان سے یہی فرماتے کہ ذرا پیچھے ہٹ جائواور ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دو.معلوم ہوتا ہے اس ابتلاء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان رئو وسا پر یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا تھا کہ اب ساری عزت اسلام کی خدمت میں ہے کسی بڑے خاندان میں سے ہونا انسان کو عزت کا مستحق نہیں بنا سکتا.جب اس طرح یکے بعد دیگرے نو مسلم غلام صحابہؓ کے آنے پر ان کو
Page 219
پیچھے ہٹنا پڑا تو ہٹتے ہٹتے وہ جوتیوںکی جگہ پر جا پہنچے یہ دیکھ کر وہ کمرہ میں سے باہر نکل گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دیکھا آج ہماری کیسی ذلت ہوئی ہے.پھر وہ افسوس کرنے لگے کہ عمر ؓ سے ہمیں اس بات کی توقع نہیں تھی.عمر ؓ تو جانتا تھا کہ ہم کتنے بڑے خاندانوں میں سے ہیں مگر افسوس کہ انہوں نے بھی ہماری عزت کی کوئی پرواہ نہ کی اور ہم پر غلاموں کو تر جیح دے دی.ان میں سے ایک جو زیادہ سمجھدار تھا اس نے جب یہ باتیں سنیں تو کہنے لگا تم کیا باتیں کر رہے ہو.کیا تم سوچتے نہیں کہ اس میں عمر ؓ کا کوئی قصور نہیں ہمارا اپنا قصور ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے متواتر اور مسلسل لوگوں سے کہا کہ آئو اور مجھ کو مان لو.مگر ہمارے باپ دادا نے ہر دفعہ ان کا انکا ر کیا اور انہیں سخت سے سخت تکالیف پہنچائیں.اب اگر ہمیں اس کا کوئی خمیازہ بھگتنا پڑا ہے تو اس میں عمرؓ کا کیا قصور ہے.ہمارے باپ دادا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا لیکن ان غلاموں نے آپ کو مان لیا اور اسلام کے لئے ہر قسم کی قربانی کی.یہی وجہ ہے کہ آج غلاموں کو ہم پر ترجیح دی گئی ہے.اگر ہمارے باپ دادا اسلام کے لیے قربانی کرتے تو ہمیں بھی عزت ملتی.جب انہوں نے اس وقت قربانی نہیں کی بلکہ اسلام کو قبول تک نہیں کیا تو آج ہمیں یہ شکوہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمارے مقابلہ میں کیوں زیادہ عزت کی گئی ہے.انہوں نے کہا یہ بات تو درست ہے مگر آخر اس ذلت کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں.ان میں سے ایک نے کہا چلو یہی بات حضرت عمر ؓ سے دریافت کر لیتے ہیں.چنانچہ وہ پھر حضرت عمرؓ کے پاس گئے اس وقت مجلس بر خاست ہو چکی تھی اور صحابہ ؓاپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا آج جو کچھ واقعہ ہواہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے ہم اس کے متعلق آپ کی خدمت میں حاضرہوئے ہیں.حضرت عمرؓ ان رئووسا کی گذشتہ شان وشوکت سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے باپ دادا مکہ میں کتنی بڑی عزت رکھتے تھے جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عمرؓ کی آنکھوں میںآنسوڈبڈبا آئے اور آپ نے فرمایا میں معذور تھا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مانا جب ساری دنیا آپ کی مخالف تھی اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی تکالیف برداشت کیں.جب خدا نے ان کو اسلام میں عزت دی تو میرا بھی فرض تھا کہ میں ان کو عزت کے مقام پر بٹھاتا.انہوں نے کہا ہم یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہمارا اپنا قصور ہے.یہ لوگ واقعہ میں اسی عزت کے مستحق تھے مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی کفارہ ایسا نہیں جس سے یہ ذلت کا داغ ہماری پیشانیوں پر سے مٹ سکے؟حضرت عمرؓ پر یہ سوال سن کر ایسی رقت طاری ہوئی کہ آپ الفاظ میں ان کو کوئی جواب نہ دے سکے صرف آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر شام کی طرف اشارہ
Page 220
کردیا.شام میں ان دنوں قیصر کی فوجوں سے اسلامی فوجوں کی جنگ ہورہی تھی اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس جنگ میں شامل ہو جائو اور اپنی جانیں اسلام کے لیے قربان کر دو تو شاید ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے.وہ نوجوان اس بات کو سمجھ گئے اسی وقت باہر نکلے،اونٹوں پر سوار ہوئے اور سب کے سب اس جنگ میں شامل ہونے چلے گئے اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آیا سب کے سب اس جنگ میں قربان ہوگئے.(مناقب امیر المؤمنین عمر بن الـخطاب لابن الـجوزی باب فی عدلہ) پس بے شک قیامت کے دن بھی خدا تعالیٰ اپنی نعمتوں کے متعلق لوگوں سے سوال کرے گا اور ان سے دریافت کرے گا کہ میری نعمتوں سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا.مگر اس دنیا میں بھی جب قوموں پر تباہی وارد ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہا کرتی ہیں کہ ہمیں ترقی کا فلاں موقع ملا مگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا فلاں موقع ملا مگر ہم نے اسے ضائع کر دیا.غرض قرآن کریم نے اس سورۃ میں نہایت مختصر الفاظ میں وہ گُر بتایا ہے جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں اگر اس گُر کو ہمیشہ یاد رکھا جائے تو کبھی قومی تباہی نہ آئے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہوشیار کر دیا تھا کہ قومی تباہی کی سب سے بڑی وجہ تکا ثر ہوتی ہے مگر افسوس کہ باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا تھا پھر بھی قومیں اسی طرح کرتی چلی جاتی ہیں.خدا تعالیٰ کی نعمتیں ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور وہ تکا ثر کو زیادہ اہمیت دے کر اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں گرا لیتی ہیں.
Page 221
سُوْرَۃُ الْعَصْـرِ مَکِّیَّۃٌ سورۃالعصریہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ ثَلَاثُ اٰیَاتٍ دُوْنَ الْبَـسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اس کی بسم ا للہ کے سوا تین آیات ہیں اور ایک رکوع ہے سورۂ عصر مکی ہے سورۃ العصر اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہے.مستشرقین کے نزدیک بھی یہ ابتدائی مکی سورتوں میں سے ہے.میور نے اسے خواطر نفسیہ ( SOLILOQUISE) میں سے قرار دیا ہے.یعنی وہ سورتیں جو اس کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمہ بالنفس سے تعلق رکھتی ہیں ان سورتوں میں اس نے سورۃ العصر کو بھی شامل کیا ہے اور چونکہ وہ ان کو بالکل ابتدائی سورتیں قرار دیتا ہے اس لئے اس کے نزدیک یہ بالکل ابتدائی مکی سورۃ ہے.(A Comprehensive Commentary on the Quran by Wherry vol:4 P:276) بعض روایات میں جو ہیں تو غیر معروف ایک عجیب واقعہ اس سورۃ کے متعلق بیان کیا گیا ہے.عمرو بن عاص سے جبکہ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے یہ روایت کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے کسی کام کے لئے مسیلمہ کذاب کے پاس گئے.اس نے پوچھا تمہارے شہر کے نبی پر کوئی تازہ کلام نازل ہوا ہے تو سنائو.عمرو بن عاص نے کہا کہ ایک مختصر سی نئی سورۃ ان پر نازل ہوئی ہے مگر ہے بڑی لطیف اور سورۃ العصر اسے سنائی.مسیلمہ نے سورۃ العصر سن کر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی پھر ایک بےہودہ سی عبارت با قافیہ پڑھ کر عمرو بن عاص کو سنائی اور کہا کہ یہ کلام ابھی مجھ پر نازل ہوا ہے.پھر پوچھا کہ آپ اس کے بارہ میں کیا کہتے ہیں.عمرو بن عاص نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو تم کو معلوم ہی ہے کہ میں تم کو جھوٹا سمجھتا ہوں (تفسیر ابن کثیر زیر سورۃ العصر ابتدائیۃ ).اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار پر بھی اس مختصر سورۃ کا ایک گہرا اثر تھا.حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ سورۃ بڑے وسیع مطالب رکھتی ہے اگر کوئی شخص اس سورۃ پر تدبّر کرے تو اس کی تمام دینی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں.(تفسیر ابن کثیر زیر سورۃ العصر ابتدائیۃ ) ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو صحابیؓ تھے جب بھی وہ آپس میں ملنے کے بعد ایک دوسرے
Page 222
سے جدا ہونے لگتے تو یہ سورۃ ایک دوسرے کو سناتے اور پھر سلام کر کے رخصت ہوتے( روح المعانی تفسیر سورۃ العصـر ابتدائیۃ).اس کے بغیر وہ کبھی جدا نہیں ہوتے تھے گویا صحابہؓ اس سورۃ کے مضمون کی وسعت سے خاص طور پر متاثر تھے.ترتیب سورۂ عصر کا پہلی سورتوں سے تعلق جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں گذشتہ چند سورتوں سے یہ طریق چلا آرہا ہے کہ ایک سورۃ اسلام کے ابتدائی زمانہ کے متعلق آتی ہے تو دوسری سورۃ اسلام کے دوسرے زمانہ کے متعلق آتی ہے.اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ اسلام کے ابتدائی زمانہ کے متعلق تھی اور وَ الْعَصْرِ.اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ آخری زمانہ کے متعلق ہے.اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیوی ترقیات کسی قوم کو تباہی سے نہیں بچا سکتیں.قوموں پر ترقی کا ایک زمانہ ایسا آیا کرتا ہے جب وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے تنزّل کی کوئی صورت نہیں.چونکہ اسلام پر بھی ایک ایسا زمانہ آنے والا تھا جب اس کے دشمنو ں نے اپنی مادی ترقیات پر نظر رکھتے ہوئے کہنا تھا کہ اب ہماری تباہی کی کوئی صورت نہیں.ادھر مسلمانوں نے دشمنوں کی حالت کو دیکھ کر سمجھ لینا تھا کہ ہمارے لیے اب ترقی کی کوئی صورت نہیںاس لیے اس زمانہ کی حالت کا نقشہ سورۃ العصر میں کھینچا گیا ہے.گویا اس میں زمانہء مسیح موعودؑ کی پیش گوئی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود بھی اس سورۃ کو اپنے زمانہ پر چسپاں فرمایا ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے(شروع کرتا ہوں) وَ الْعَصْرِۙ۰۰۲ (مجھے) قسم ہے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ) زمانہ کی اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍۙ۰۰۳ (کہ ) یقیناً (نبیوں کا مخالف ) انسان ( ہمیشہ ہی )گھاٹے میں ( رہتا ) ہے حلّ لُغات.عَصْـرٌ.عَصْـرٌ کہتے ہیں عَصَـرَ الْعِنَبَ وَ نَـحْوَہٗ عَصْـرًا: اِسْتَخْرَجَ مَآءَہٗ.انگور نچوڑ
Page 223
کر اس کا پانی نکالااور عَصَـرَ الشَّیْءَ عَنْہُ کے معنے ہوتے ہیں مَنَعَہٗ ایک چیز کو دوسری چیز کے پاس پہنچنے سے روک دیا اور عَصَـرَ فُلَانًا کے معنے ہوتے ہیں اَعْطَاہُ الْعَطِیَّۃَ اسے تحفہ دیا.اور عَصَـرَہٗ کے معنے ہوتے ہیں حَبَسَہٗ اس کو روک دیا (اقرب) اور عَصْـرٌ اس کا مصدر ہے.اس لئے سب مصدری معنے بھی اس میں پائے جاتے ہیں.اس کے علاوہ عصر دن کو بھی کہتے ہیں اور عصر کے معنے رات کے بھی ہوتے ہیں اور عصر کے معنے سورج ڈھلنے سے لے کر شام کے وقت تک کے بھی ہیں اور عصر کے معنے صبح سے لے کر سورج کے ڈھلنے تک کے بھی ہیں (اقرب).گویا یہ لفظ اپنے اندر متضاد معنے رکھتا ہے.اس کے معنے دن کے بھی ہیں یعنی وہ دن جس میں سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ دن کا لفظ عام طور پر رات اور دن دونوں کے لئے بولا جا تا ہے اور اس کے معنے رات کے بھی ہیں.اسی طرح اس کے معنے صبح سے زوال تک کے بھی ہیں اور زوال سے شام تک کے بھی ہیں.اس کی جمع اَعْصُـرٌ وَ عُصُوْرٌ آتی ہے اور اس کے معنے علاوہ اوپر کے معانی کے قبیلہ کے بھی ہوتے ہیں.چنانچہ لغت میں لکھا ہے اَلْعَصْـرُ: اَلرَّہْطُ وَالْعَشِیْـرَۃُ اور عصر کے معنے اَلْمَطْرُ مِنَ الُمُعْصِـرَاتِ کے بھی ہیں.یعنی تیز گھنی بدلیوں میں سے جو بارش برستی ہے اسے بھی عصر کہتے ہیں.اور عصر کے معنے تحفہ اور انعام کے بھی ہوتے ہیں اور عَصْـٌر، عِصْـرٌ، عُصْـرٌ: دَھْرٌ یعنی زمانہ کے معنوں پر بھی بولا جاتا ہے.اس وقت اس کی جمع پہلی جمع کے علاوہ ایک اور بھی استعمال ہوتی ہے.پہلے معنوں کے لحاظ سے تو اس کی جمع صرف اَعْصُـرٌ وَعُصُوْرٌ ہوتی ہے لیکن زمانہ کے معنوں میں اس کی جمع اَعْصُـرٌ بھی ہے عُصُوْرٌ بھی ہے اور اِعْصَارٌ بھی ہے.پھر آگے اِعْصَارٌکی جَـمْعُ الْـجَمْعِ اَعَاصِـر آتی ہے(اقرب).وَالْعَصْرِ میں وائو قسم کی ہے اور وَ الْعَصْرِ کے معنے یہ ہیں کہ ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں عصر کو.کس بات کی شہادت کے طور پر؟وہ دوسری آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ یعنی انسان یقیناً گھاٹے میں ہے.خُسْـرٌ.خُسْـرٌکے معنے گھاٹے کے ہوتے ہیں چنانچہ خَسِـرَ التَّاجِرُ فِیْ بَیْعِہٖ(خَسْـرًا وَ خَسَـرًا وَخُسُـرًا وَخُسْـرَانًا وَ خَسَـارَۃً) کے معنے ہوتے ہیں وُضِعَ فِیْ تِـجَارَتِہٖ اس نے اپنی تجارت میں نقصان اٹھایا وَ ضِدُّ رَبِـحَ اور یہ نفع کے مقابل کا لفظ ہے.یعنی اس کے معنے گھاٹے کے ہوتے ہیں اسی طرح جب خَسِـرَا الرَّجُلُ کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں ضَلَّ وہ گمراہ ہو گیا.لیکن کبھی اس کے معنے ہَلَکَ کے بھی ہوتے ہیں یعنی وہ ہلاک ہو گیا (اقرب) پس اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ کے معنے یہ ہوئے کہ انسان یقیناً گھاٹے میں ہے یا انسان یقیناً گمراہی میں مبتلا ہے یا انسان یقیناً ہلاکت کی طرف جا رہا ہے.تفسیر.عصر کے مختلف معانی کے اعتبار سے وَ الْعَصْرِ کا مطلب عصر کے مختلف معانی
Page 224
جو اوپر بتائے گئے ہیں ان کے لحاظ سے اس آیت کے بھی مختلف معانی ہوجائیں گے.عصر کے ایک معنے دن کے پہلے حصہ یعنی صبح سے دوپہر تک کے ہیں اور دوسرے معنے دن کے پچھلے حصہ یعنی دوپہر سے شام تک کے ہیں.چونکہ قرآن کریم اپنے مطالب میں ذوالوجوہ ہے اور اس کی ایک ایک آیت اپنے اندر کئی بطون رکھتی ہے اس لئے جتنے معنے کسی لفظ کے لغتََا یا محاورۃََ ہو سکتے ہوں اور وہ کسی آیت پر چسپاں بھی ہوتے ہوں ہم ان تمام معانی کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں.اس نقطہ نگاہ کے ماتحت اگر عصر کے معنے دن کے پہلے اور پچھلے حصہ کے کئے جائیں تو اس جگہ عرفی دن جس کا مادی سورج کے ساتھ تعلق ہے وہ مراد نہیں ہو گا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت مراد ہو گا.کیونکہ قرآن کریم نے صراحتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیا ہے جیسا کہ سورۃ الشمس میں اس کا ذکر آتا ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہوئے تو لازمی طور پر آپ کا زمانہ دن کہلائے گا اورایک دن کا ابتدائی حصہ ہو گا اور ایک آخری حصہ ہوگا.پس عصر کے معنے اگر ہم دن کے ابتدائی اور آخری حصہ کے لیںتو جہاں مادی طور پر روزانہ چڑھنے والے سورج کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے دن کا ایک ابتدائی حصہ مراد لیتے ہیں اور ایک آخری حصہ مراد لیتے ہیں.وہاں قرآن کریم نے چونکہ خصوصیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا نام دن رکھا ہے اس لئے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم زمانہء نبوت محمدیہ کے ابتدائی حصے کو بھی تمہارے سامنے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ہم زمانہء نبوت محمدیہ کے آخری حصہ کو بھی تمہارے سامنے بطور شہادت پیش کرتے ہیں.اگر تم ان دونوں حصوں کو دیکھو گے اور ان پر غور اور تدبر سے کام لو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ انسان یقیناً گھاٹے میں ہے.ان معنوں کے رو سے اَلْاِنْسَان سے وہ انسان سمجھا جائے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کھڑا ہوا.کیونکہ ہر جگہ الفاظ کے ان کی نسبت کے لحاظ سے معنے ہوتے ہیں.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہوئے تو گھاٹا پانے والا انسان بہرحال وہی ہوا جس نے سورج سے فائدہ نہ اٹھایا.پس اَلْاِنْسَان سے اس جگہ سورج کے مخالف کھڑا ہونے والا انسان مراد ہے.یعنی وہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلٖ وسلم کی بعثت سے فائدہ نہ اٹھایا.بالخصوص اس وجہ سے بھی اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ میں مومنوں کا استثنیٰ کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اَلْاِنْسَان سے غیرمومن انسان مراد ہیں نہ کہ مومن.اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ میں انسان سے مراد کافر انسان یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ کفار کو اَلْاِنْسَان کیوں کہا گیا ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کو اَلْاِنْسَان اس لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ
Page 225
سے یہ سنت چلی آئی ہے کہ جب بھی اس کی طرف سے کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے اس پر ابتدا میں ایمان لانے والے عام طور پر ادنیٰ طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں.بے شک وہ عالم ہوں، متقی ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے والے ہوں، دینی امور میں نہایت بالغ نظر رکھنے والے ہوں، روحانیت اور تقویٰ کے بلند مقام تک پہنچے ہوئے ہوں پھر بھی دنیوی لحاظ سے وہ ادنیٰ طبقہ میں شمار کئے جاتے ہیں.کیونکہ ان کے پاس نہ دولت ہوتی ہے نہ حکومت ہوتی ہے نہ ظاہری طاقت ہوتی ہے اور ان کے دشمن ان میں سے ایک ایک چیز کے مالک ہوتے ہیں.وہ صاحب دولت بھی ہوتے ہیں، وہ صاحب وجاہت بھی ہوتے ہیں اور وہ صاحب حکومت بھی ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ ان کو کسی گنتی اور شمار میں نہیں سمجھتے.ہمارے ہاں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے.چنانچہ جب کسی کی تحقیر کرنی ہو تو کہا جاتا ہے وہ کون سی گنتی میں ہے یا کہا جاتا ہے وہ بھی کوئی آدمی ہے.پس اَلْاِنْسَان میں کفار کی اسی ذہنیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمان ان کی نگاہ میں ایسے بے حقیقت ہیں کہ وہ ان کو انسانوں میں شمار ہی نہیں کرتے.صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں.پس چونکہ کفار نبیوں کے اتباع کے متعلق ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی آدمی ہیں.آدمی تو ہم ہیں.اس لئے اللہ تعالیٰ ان کے مقابل میں طنزیہ رنگ اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے یہ جو اپنے آپ کو آدمی سمجھتے اور اَلْاِنْسَان قرار دیتے ہیں ہم عصر کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تباہی اور بربادی کی طرف جارہے ہیں.یہ اپنے آپ کو بے شک انسان قرار دیں اور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے رہیں کہ وہ بھی کوئی آدمی ہیں.حقیقت یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو انسان قرار دینے والے اور دوسروں کو دائرہ انسانیت سے خارج سمجھنے والے تباہی اور بربادی کے راستہ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں.گویا جس لفظ سے وہ اپنے آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور جس لفظ کا استعمال وہ اپنے لئے فخر کا موجب سمجھتے تھے اسی کو طنزیہ طور پر ان کے لئے استعمال کیا گیا ہے.جیسے قرآن کریم میںایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذُقْ١ۙۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ( الدّخان:۵۰) جب دوزخی دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسے کہا جائے گا کہ تو اس عذاب کا مزہ چکھ.تُو تو بڑا عزت والا ہے تُو تو بڑے رتبے والا ہے.حالانکہ وہ اس وقت دوزخ میں داخل کیا جا رہا ہوگا اور اس لحاظ سے اس کی عزت اور رتبے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.اگر وہ عزت والا ہوتا تو دوزخ میں کیوں ڈالا جاتا اور اگر رتبے والا ہوتا تو آخرت میں کیوں ذلیل ہوتا.اس کا دوزخ میں ڈالا جانا ہی بتاتا ہے کہ نہ اسے عزت حاصل تھی اور نہ اسے رتبہ حاصل تھا.مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ دوزخ میں ڈالتے وقت اسے کہا جائے گا ذُقْ١ۙۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ.اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ طنزیہ طور پر ان الفاظ کو استعمال کیا گیا
Page 226
ہے اور مطلب یہ ہے کہ تُو تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا عزیز ہوں اور تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا کریم ہوں.آج تو دوزخ میں جا اور دیکھ کہ تیرے عزیز اور کریم ہونے کا دعویٰ کہاں تک حق بجانب تھا.اسی طرح اَلْاِنْسَان میں وہ دعویٰ انسانیت مراد ہے جو دشمنان اسلام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آدمی تو ہم ہیں یہ بھلا کس گنتی اور شمار میں ہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے گنتی اور شمار والے انسان تجھے پتہ لگ جائے گا کہ تو گھاٹے کی طرف جا رہا ہے تیرے دعوے سب خاک میں مل جائیں گے اور جن لوگوں کو تو حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتا کہ وہ بھی کوئی انسان ہیں ان بظاہر ادنیٰ نظر آنے والے لوگوں کے مقابلہ میں تجھے ایسی ذلت اور رسوائی نصیب ہو گی کہ دنیا تیرے وجود سے عبرت حاصل کرے گی.آخر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اَلْاِنْسَان کیوں کہتے تھے.ان کا اپنے آپ کو اَلْاِنْسَان کہنا اس وجہ سے تھا کہ جو چیزیں ان کے پاس تھیںان کی وجہ سے لوگ یقینی طور پر جیتا کرتے ہیں اور جو چیزیں مسلمانوں کے پاس نہیں تھیں ان کا فقدان لوگوں کے لئے یقینی طور پر شکست کا موجب ہوا کرتا ہے.مثلا ً وہ اپنے آپ کو اَلْاِنْسَان اس لئے کہتے تھے کہ ہم حاکم ہیں اور مسلمان محکوم ہیں اور یہ ایک واضح امر ہے کہ دنیا میں عام طور پر حاکم ہی جیتا کرتے ہیں محکوم نہیں جیتا کرتے.بے شک حاکم بھی بعض دفعہ ہار جاتے ہیں مگر اس وقت جب رعایا ان کے خلاف ہو.اگر رعایا ان کے ساتھ ہوتووہ شکست نہیں کھاتے.اسی طرح جب وہ کہتے تھے کہ ہم آدمی ہیں مسلمان بھلا کس گنتی اور شمار میں ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم تو کثیر ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے.اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ (الشعرآء:۵۵) انہوں نے ہمارے مقابلہ میں کیا فتح حاصل کرنی ہے.اور یہ بھی ایک واضح امر ہے کہ عام طور پر اکثریت ہی فتح حاصل کرتی ہے اقلیت فتح حاصل نہیں کرتی.پھر قوموں کو جتھہ غلبہ دیا کرتا ہے اور یہ جتھہ بھی اہل مکہ کے پاس تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا.اسی طرح قوموں کودولت سے غلبہ حاصل ہوا کرتا ہے مگر دولت بھی دشمنوں کے پاس تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی.قوموں کو سیاست اور اردگرد کی اقوام سے دوستانہ تعلقات کے نتیجہ میں غلبہ حاصل ہوا کرتا ہے مگر سیاست بھی دشمنوں کے قبضہ میں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ میں نہیں تھی.قوموں کو صنعت وحرفت سے غلبہ حاصل ہوا کرتا ہے مگر صنعت وحرفت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ کفار مکہ کے ہاتھ میں تھی.غرض جتنی چیزیں دنیا میں کسی قوم کو ترقی دینے کا موجب ہوتی ہیں وہ سب کی سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ہاتھ میں تھیں.اور جتنی چیزیں بظاہر کسی قوم کی شکست کا موجب ہوتی ہیں وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوںمیں پائی جاتی تھیں.پس فرماتا ہے بے شک تم اپنے متعلق کہتے ہو کہ ہم آدمی ہیں اور ہم بھی
Page 227
تسلیم کرتے ہیں کہ تمہارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو انسان کو انسان بنا دیتی ہیں.تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس دولت بھی ہے، تمہارے پاس سیاست بھی ہے، تمہارے پاس صنعت وحرفت بھی ہے، تمہارے پاس تجارت بھی ہے، غرض وہ سب چیزیں تمہارے پاس ہیں جن سے دنیا میں قوموں کو عروج حاصل ہوا کرتا ہے مگر باوجود یہ تسلیم کر لینے کے کہ اَلْاِنْسَان کہلانے کے تم ہی مستحق ہو.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی دنیوی نقطہء نگاہ سے کسی گنتی اور شمار میں نہیں ہیں پھر بھی ہم بطور پیش گوئی کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے کامل انسان ! اے ہر قسم کے سازوسامان رکھنے والے انسان !اس زمانہء محمدیہ میں تیرے سازوسامان تیرے کام نہیں آئیں گے اور تو گھاٹے میں ہی رہے گا.بے شک دنیا میں عام طور پر یہ قانون جاری ہے کہ جب کسی کے پاس سیاست ہو، جب کسی کے پاس جتھہ ہو، جب کسی کے پاس علم ہو، جب کسی کے پاس حکومت ہو، جب کسی کے پاس دولت ہو، جب کسی کے پاس صنعت و حرفت ہو تو ایسا شخص ضرور جیتا کرتا ہے.مگر یہاں ایسا نہیں ہوگا.اب زمانہء نبوت محمدیہ آگیا ہے اور اب اس قانون کی بجائے ایک اور قانون جاری کر دیا گیا ہے.اب دولت کے باوجود تم ہاروگے، سیاست کے باوجود تم ہاروگے، جتھہ کے باوجود تم ہاروگے، علم کے باوجود تم ہاروگے، حکومت کے باوجود تم ہاروگے، صنعت و حرفت کے باوجود تم ہاروگے، اور تمہارا یہ ہارنااس بات کا ثبوت ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ رسالت میں سچے ہیں.ورنہ اگر کسی کے پاس جتھہ نہ ہو تو اس کا ہارنا کون سا ہارنا ہے، اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس کا ہارنا کون سا ہارنا ہے، اگرکسی کے پاس حکومت نہ ہو تو اس کا ہارنا کون سا ہارنا ہے، اگر کسی کے پاس سیاست نہ ہو تو اس کا ہارنا کون سا ہارنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے کسی قوم کا گھاٹے میں چلے جانا اصل گھاٹا ہے اور یہی وہ تنزّل اور بربادی کا مقام ہے جس کی اہل مکہ کو ان الفاظ میں خبر دی گئی ہے کہ وَ الْعَصْرِ.اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ.ہم اس زمانہ کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انسان دنیوی طور پر خواہ کتنے سازوسامان رکھتا ہو خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ ضرور گھاٹے میں چلا جاتا ہے.اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس بات کی شہادت ہوئی؟اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں عام قاعدہ یہ ہے کہ دنیوی سامانوں سے قومیں جیتا کرتی ہیں ہارا نہیں کرتیں.اسی وجہ سے لوگ کہا کرتے ہیںکہ چونکہ دنیا میںتعلیم سے ترقی حاصل ہوتی ہے ہمیں بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے یا چونکہ سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے دنیا میں ترقی ہوتی ہے اس لیے ہمیں بھی سیاست میں حصہ لینا چاہیے.وہ اپنی تمام ترقی دنیوی تدابیر سے وابستہ قرار دیتے ہیںاور خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ترقی کرنا چاہے تو اس کے لئے واحد طریق یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیوی سامان اپنے پاس
Page 228
زیادہ سے زیادہ رکھے اس کے پاس علم بھی ہو،اس کے پاس دولت بھی ہو،اس کے پاس طاقت بھی ہو، اس کے پاس جتھہ بھی ہو، اس کے پاس صنعت و حرفت بھی ہو.اور جب کسی کو یہ تمام چیزیں میسر آجائیں تو وہ خیال کرتا ہے کہ اب اس کا ترقی نہ کرسکنا بالکل محال اور ناممکن ہے.چونکہ عام طور پر دنیا میں ہمیں یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ قومی ترقی دنیوی تدابیر سے وابستہ ہوتی ہے اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا تو ترقی حاصل کرو گے اور اگر عمل نہ کیا تو گر جائو گے.تو وہ لوگ جو دنیوی تدابیر کو ہی ہر قسم کی کامیابیوں کا علاج سمجھتے ہیں حقارت آمیزہنسی ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا توہمیں ترقی ہو گی اور اگر عمل نہ کیا تو ترقی نہیں ہوگی.دنیا میں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو شخص دنیوی تدابیر کو اپنے کمال تک پہنچا دیتا ہے وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاتا ہے خواہ وہ خدا تعالیٰ کے شرعی احکام کاکتنا ہی منکر ہو اور جب حالت یہ ہے تو تمہارا اللہ تعالیٰ کے وجود کو پیش کرنا اور کہنا کہ خدا تعالیٰ کے احکام سے انحراف کیا تو تم تنزّل میں گر جائو گے بالکل خلاف عقل امر ہے.خدا تعالیٰ کی حکومت تو ہمیں اس دنیا میں نظر ہی نہیں آتی.دنیا خدا تعالیٰ کی منکر ہوتی ہے مگر پھر بھی ترقی کر جاتی ہے.اور جب دنیوی تدابیر سے کام لینے کے نتیجہ میں ہی تمام کارخانہ عالم چل رہا ہے تو ہمیں تمہاری بات کا یقین کیونکر آئے اور کس طرح پتہ لگے کہ خدا تعالیٰ کی حکومت اور اس کا رعب اور دبدبہ بھی اس دنیامیں جاری ہے.ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ خدا تعالیٰ سے باغی ہوتے ہیں مگر پھر بھی ترقی حاصل کر لیتے ہیں.پس اگر تمہاری یہ بات اپنے اندر کوئی وزن رکھتی ہے تو تم خدا تعالیٰ کی حکومت کا ہمارے سامنے کوئی ثبوت پیش کرو.ورنہ یہ ایک واضح امر ہے کہ دنیوی ترقیات میں خدا تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں.یہ چیز محض دنیوی تدابیر سے وابستہ ہوتی ہے.جو شخص ان تدابیرمیں پورا حصہ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو نہیں لیتا وہ ناکام رہتا ہے.اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی وقت دنیوی تدابیر سے کام لے کر بعض لوگوں کا دنیا پر غالب آجانا یا ترقی کرنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ خدا تعالیٰ کی حکومت اس دنیا میں نہیں.کیونکہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے جب دنیا کے پاس اپنی ترقی کے تمام سامان موجود ہوتے ہیں.مگر جب کوئی نبی آتا ہے تو اکیلا نبی ساری دنیا کے مقابلہ میں جیت جاتا ہے اور سازو سامان رکھنے والے ناکامی اور نامرادی سے حصہ لیتے ہیں.اس وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا ہے.ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ اکیلا شخص تو جیت جاتا اور ساری دنیا اپنے تمام سامانوں کے ساتھ شکست کھا جاتی پس فرماتا ہے وَ الْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ.یہ جواصول ہے کہ خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرکے کوئی انسان جیت نہیں سکتا اس اصول کو ہر زمانہ میں نہیں دیکھا جاسکتا.صرف زمانہ نبوت میں دیکھا جا سکتا ہے.وہ وقت
Page 229
ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت اور جلال کا اظہار کرتا ہے.اگر اس وقت بھی لوگ جیت جائیں تو بے شک کہا جا سکتا ہے کہ جب زمانہ نبوت میں بھی لوگ غالب آگئے تو خدا تعا لیٰ کی خدائی اور اس کی حکومت کا کیا ثبوت رہا.مگر جب اس زمانہ میں دنیا اپنے تمام سامانوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوتی اور وہ اپنی ہر تدبیر میں بری طرح ناکامی کا منہ دیکھتی ہے تو یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ دنیا پر خدا کی حکومت ہے.اگر کسی زمانہ میں وہ اپنی حکومت ظاہر نہیں کرتا تو اس سے اس کی حکومت کی نفی نہیں ہو جاتی.زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی حکومت ظاہر نہیں کر نا چاہتا ورنہ اس کی حکومت کی نفی نہیں ہو سکتی کیونکہ زمانہ نبوت میں جب وہ اپنی حکومت ظاہر کرتا ہے تو ساری دنیا اپنے سارے سامانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے نبی کے مقابلہ میں شکست کھا جاتی ہے.غرض خدا تعالیٰ کی حکومت اور اس کے دبدبہ اوراس کی شوکت کا فیصلہ صرف زمانہ نبوت سے ہوا کرتا ہے.اگر زمانہ نبوت نہ ہو تو دنیا کو دیکھ کر یہ قیاس کر لینا کہ چونکہ دنیا نے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کئے بغیر بڑی ترقی حاصل کرلی ہے اس لئے معلوم ہوا کہ دنیا پر خدا تعالیٰ کی حکومت نہیں بالکل غلط اور باطل خیال ہو گا.کیونکہ اگر دنیا پر اس کی حکومت نہیں تو وجہ کیا ہے کہ زمانہ نبوت میں ایک کمزور انسان جو ہر قسم کے سامانوں سے تہیدست ہوتا ہے ساری دنیا کے مقابلہ میں جیت جاتا ہے.آخر اس کی کوئی طبعی وجہ ہونی چاہیے اور چونکہ طبعی وجہ کوئی نہیں، ادھر ہمیں ایک نبی کا دعویٰ نظر آتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور وہ مجھے مخالف حالات کے باوجود کامیابی عطا فرمائے گا تو یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ واقعہ میں خدا تعالیٰ کی حکومت اس دنیا پر جاری ہے.دنیا میں بھی دیکھ لو ماں باپ کے پاس کئی دفعہ بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں مگر وہ ان کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتے.لیکن ایک اور وقت ایسا آتا ہے جب کوئی بچہ ذرا بھی شور ڈالتا ہے تو باپ اسے ایک تھپڑ رسید کر دیتا ہے اور وہ اسی وقت خاموش ہو جاتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ باپ کی حکومت موجود ہے.اسی طرح بعض دفعہ ایک طالب علم سبق یاد کرکے سکول میں نہیں جاتا تو استاد اسے کچھ بھی نہیں کہتا.مگر ایک دن جب وہ سبق نہیں سناتا تواستاد اسے بید کی سزا دے دیتا ہے اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ استاد کی حکومت موجود ہے.پس کسی وقت ماں باپ کا اپنے بچوں کو خاموش نہ کرانا یا استاد کا اپنے شاگرد کو بید کی سزا نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی بچوں پر حکومت نہیں یا استاد کی شاگردوں پر حکومت نہیں.کیونکہ جب ماں باپ یا استاد سزا دیتے ہیں ہر ایک کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کی حکومت موجود تھی.صرف اتنی بات تھی کہ پہلے انہوں نے اس حکومت سے کام نہیں لیا تھا.اسی طرح بیسیوںدفعہ لوگ گورنمنٹ کے خلاف شور مچاتے ہیں مگر گورنمنٹ ان کے متعلق کوئی کارروائی نہیں کرتی.لیکن ایک دن آتا ہے جب حکومت کے خلاف کوئی ذرا بھی شور مچائے
Page 230
تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے.اب اگر گورنمنٹ کچھ عرصہ تک کسی کو گرفتار نہیں کرتی تو اس کے یہ معنے نہیں ہو تے کہ گورنمنٹ موجود نہیں کیونکہ دوسرے وقت حکومت اسے گرفتار کر کے سزا دے دیتی ہے جو ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ گورنمنٹ موجود ہے پس گورنمنٹ کا کسی کو نہ پکڑنا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ حکومت نہیں بلکہ اس کا پکڑنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ حکومت ہے.یہی دلیل اللہ تعالیٰ اس جگہ بیان کرتا ہے کہ زمانہ نبوت محمدیہؐ کو ہم اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیںکہ انسان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے طور پر کبھی ترقی نہیں کر سکتا.اور اگر کرتا ہے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے ڈھیل دی گئی ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب خدا چاہتا ہے کہ دنیا اس کے احکام کے تابع چلے تو وہ اپنا نبی لوگوں میں بھیج دیتا ہے.پھر خواہ دنیا کے پاس کتنے بڑے سامان ہوںوہ ان سے کام لے کر کبھی جیت نہیں سکتی.عَصْـر کے دوسرے معنے دن کے آخری حصہ کے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے وَ الْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ کا مفہوم یہ ہے کہ جب اسلام پر تنزّل کا زمانہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے احیا ء کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مبعوث فرمائے گا اس وقت پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے پاس کسی قسم کے ظاہری سامان نہیں ہوں گے.دنیا سمجھے گی کہ دشمن بڑا طاقتور اور قوی ہے.لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سخت کمزور ہے.یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جیت جائے اور دشمن اپنے تمام سازو سامان کے ساتھ شکست کھا جائے.مگر باوجود اس حقیقت کے کہ دشمن طاقتور ہو گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سخت کمزور ہوں گے آخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ.ان کے مقابل کے دشمن جو یہ کہا کریں گے کہ ہم ہی انسان ہیں یہ ہمارے مقابلہ میں بھلا کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ انسان کہلانے والے ہار جائیں گے اور جن کو کسی گنتی میں نہیں سمجھا جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے پہلے زمانہ میں لوگوں کو اس اصول کی صداقت کا تجربہ ہو چکا ہے.دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کوذلیل سمجھا کرتے تھے ہار گئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سامان نہ رکھنے کے باوجود جیت گئے اور پھر فتح و کامیابی کا یہ زمانہ چند سالوں تک نہیں رہا بلکہ صدیوں تک چلتا چلا گیا.مسلمانوں نے اس وقت سائنس کی ایجادات میں خا ص طور پر دسترس حاصل نہیں کر لی تھی.نہ ان میں تجارت کا کوئی خاص ملکہ پیدا ہو گیا تھا.نہ انہیں علمی لحاظ سے دوسروں پر کوئی غیر معمولی فوقیت حاصل تھی.وہ ویسی ہی تجارت کرتے تھے جیسے دوسرے لوگ تجارت کرتے ہیںویسا ہی ان کے پاس مال تھا جیسے دوسروں کے پاس مال تھا.
Page 231
ویسا ہی ان کا علم تھا جیسے دوسروں کا علم تھا.مگر اس کے باوجود اللہ تعا لیٰ نے ہر قسم کی ترقی اسلام کی وابستگی کے ساتھ مخصوص کر دی تھی نہ یورپ میں یہ خوبی پائی جاتی تھی، نہ چین میں یہ خوبی پائی جاتی تھی، نہ جاپان میں یہ خوبی پائی جاتی تھی مگر جو مسلمانوں سے ملتا تھااس میں ترقی کی روح پیدا ہو جاتی تھی.اسی طرح علوم مو جو د تھے،محنت کرنے والی قومیں موجود تھیں،روپیہ خرچ کرنے والے لوگ موجود تھے مگر اسلام کے سوااور کوئی چیز دنیا کو صدیوں تک ترقی کی طرف نہ لے جا سکی.آخر وجہ کیا ہے کہ انسانی تدا بیراس وقت ناکارہ ہو گئیں ؟اس کی وجہ در حقیقت یہی تھی کہ وہ زما نہ ظہو رنبوت تھا جس میں خدا تعا لیٰ کا ایک نیاقانون جاری ہو جاتا ہے اور جس میں محض دنیوی تدابیر سے کام نہیں چل سکتا بلکہ ایمان کو عمل کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے.اس وقت خدا تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی دنیا کی ترقی ہے.جو شخص اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں شامل کر لے گا وہ جیت جائے گا اور جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں شامل نہیں کرے گا وہ ہار جائے گا.چنانچہ ایسا ہی ہوا.ہر قوم جو اسلام سے دور رہی ترقی سے بھی دور رہی اور ہر قوم جو اسلام سے وابستہ ہوئی وہ ترقی سے بھی ہمکنار ہوگئی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نظارہ تم اسلام کے ابتدائی زمانہ میں دیکھ چکے ہو ویسا ہی نظارہ اسلام کے آخری زمانہ میں بھی رونما ہوگا.چنانچہ اب جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوئی ہے اس زمانہ میں بھی ایسی قومیں موجود ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم ہی انسان ہیں.چنانچہ جب ہیو مینی ٹیرین(HUMANITARIAN) کا لفظ استعمال کرتی ہیں.تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یورپ کے لوگوںکو یورپ کے لوگوں سے سختی نہیں کرنی چاہیے یا امریکہ کے لوگوں کو امریکہ کے لوگوں سے سختی نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مفہوم نہیں ہوتا.اسی طرح جب وہ حریت و مساوات کے نعرے بلند کرتے ہیںتو اس حریت اور آزادی سے بھی ان کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ مغربی لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے ایشیا کے لوگ ان کے ذہن کے کسی گوشہ میں بھی نہیں ہوتے کیونکہ ایشیا والوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے.پس فرماتا ہے وہ زمانہ پھر آنے والا ہے جب دنیا کا ایک طبقہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہوئے باقی سب دنیا کو ذلیل قرار دے گا.اس زمانہء نبوت میں بھی باوجود اس کے کہ دشمنان اسلام کے پاس ہر قسم کے سامان ہوں گے اور دنیا ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے کہے گی کہ یہ لوگ کبھی ہار نہیں سکتے.ان کی شوکت کبھی مٹ نہیں سکتی.ان کا رعب اور دبدبہ کبھی زائل نہیں ہو سکتا.ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ چونکہ وہ زمانہ نبوت ہوگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانہ میں دوسری بعثت ہو گی اس لیے باوجود سامان رکھنے کے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزور نظر
Page 232
آنے والی جماعت کے مقابلہ میں ہار جائیں گے ان کی طاقت کچل دی جائے گی اور یہ نشان دنیا میں پھر ظاہر ہوگا کہ زمانہ نبوت میں جو قوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے مقابلہ میں کھڑی ہوتی ہے وہ یقیناً خسران وتباب میں رہتی ہے.بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ نبی پر ایمان لائے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی.دنیا کی ترقی تو دنیوی سامانوں سے وابستہ ہے نہ کہ ایمان باللہ اور ایمان با لرسل کے ساتھ.جب دنیا میں ہمیشہ سے وہی اقوام جیتتی چلی آئی ہیں جو اپنے ساتھ دنیوی سامان رکھا کرتی ہیں تو اس نظریہ کے خلاف تم یہ نیا نظریہ کیوں پیش کر رہے ہو کہ جب تک لوگ اللہ تعالیٰ کے مامور پر ایمان نہ لائیں وہ کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتے.آج کل بھی احمدیت کے مقابلہ میں مسلم اور غیر مسلم دونوں طبقوں کی طرف سے یہ سوال پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ترقی کا اصل ذریعہ تو یہ ہے کہ مدرسے جاری کئے جائیںیونیورسٹیاں بنائی جائیں، کارخانے قائم کئے جائیں، صنعت وحرفت کو فروغ دیا جائے، سیاسی امور میں حصہ لیا جائے، اپنی طاقت اور جتھہ کو بڑھایا جائے، نہ یہ کہ ان امور کی طرف تو توجہ نہ کی جائے اور نبی پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی جائے.نبی پر ایمان لانا کسی قوم کو ترقی نہیں دے سکتا.ترقی کی صورت صرف یہی ہے کہ دنیوی تدابیر کو اپنے کمال تک پہنچا دیا جائے اور ہر قسم کے مادی سامان جو ترقی کے لئے ضروری ہوتے ہیں ان کو جمع کیا جائے.اس کا جواب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں دنیا دنیوی اسباب سے ترقی کرتی ہے لیکن زمانہ نبوت میں دنیوی اسباب سے نہیں بلکہ روحانی اسباب سے ترقی کیا کرتی ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور تا دنیا دین کی خادم ثابت ہو.اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی باد شاہت دنیا پر ثابت نہیں ہو سکتی وہ بادشاہت جس کے متعلق حضرت مسیح ناصریؑ نے بھی دعا کی اور کہا کہ اے خدا جس طرح تیری بادشاہت آسمان پر ہے ویسی ہی زمین پر بھی آئے(متی باب ۶ آیت ۱۰).اگر دنیا ہمیشہ دنیوی سامانوں سے جیتتی چلی جائے تو لوگو ں کو خدا تعالیٰ کی باد شاہت کا کس طرح پتہ لگ سکتا ہے اور وہ کیونکر معلوم کر سکتے ہیںکہ ایک زندہ خدا موجود ہے جس کے منشاء کے خلاف اگر دنیا کی تمام طاقتیں بھی متحد ہو جائیںتو وہ خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن کر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں.یقیناً اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت سے لوگ ہدایت پانے سے محروم رہ جاتے اور اکثر لوگوں پر دین کی برتری مشتبہ ہوجاتی مگر جب دنیوی سامانوںکے خلاف ہوتے ہوئے ایک نبی خبر دیتا ہے کہ میں جیت جائوںگا اور میرے مقابلہ میں جس قدر طاقتیں کھڑی ہیںوہ ہر قسم کے سامان رکھنے کے باوجود ناکام رہیں گی اور پھر واقعہ میں ایسا ہی ہو جاتا ہے تویہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ خدا کی حکومت دنیا میں موجود ہے.آج یورپین مصنّف بڑے زور سے لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں کامیاب ہو گئے تو
Page 233
اس میں اچنبھے کی کوئی بات نہیں.قیصر کی حکومت اس وقت اپنے اندرونی زوال کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی.کسریٰ کی حکومت میں ضعف و اختلال کے آثار پیدا ہوچکے تھے اور سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومتیں اب جلد مٹ جانے والی ہیں.ایسی حکومتوں پر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آگئے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جسے معجزہ قرار دیاجاسکے.مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا عرب کی حالت قیصر وکسریٰ کی حکومتوں سے اچھی تھی؟ اگر اچھی ہوتی تب تو کہا جاسکتا تھا کہ چونکہ عرب کی حالت اچھی تھی اور قیصر و کسریٰ کی حالت خراب تھی اس لئے اہل عرب نے قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو تاراج کردیا.مگر ہر شخص جو تاریخ سے معمولی واقفیت بھی رکھتا ہے جانتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے مقابلہ میں عرب کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی.پس سوال یہ ہے کہ کیا قیصر و کسریٰ کی حکومتوں نے عرب کے مقابلہ میں ہی ٹوٹنا تھا اور پھر ان عربوں کے مقابلہ میں جن کا اپنا حال خراب تھا اور کیا عرب کے لوگوں میں سے بھی اس شخص کے ہاتھ سے قیصر و کسریٰ کی حکومتوںنے پاش پاش ہونا تھا جس کوکچلنے کے لئے خود عرب کے لوگ کھڑے ہوگئے تھے؟ اور وہ سمجھتے تھے کہ قیصر و کسریٰ تو الگ رہے، عرب کے لوگ تو الگ رہے صرف مکہ کے رہنے والے ہی اس کو کچلنے کے لئے کافی ہیں.ہر شخص جو حالات پر غور کرکے صحیح نتائج اخذ کرنے کا ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو وہ اکیلا شخص پاش پاش کرنے کی اپنے اندر اہلیت رکھتا تھا جس کے متعلق خود مکہ کی بستی والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مقابلہ میں بھی نہیں ٹھہر سکتا ہم اسے کچل کر رکھ دیں گے.مگر جب مکہ کی بستی والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو مٹادیں گے اس وقت وہ اپنی کمزوری کے باوجود دنیا کو پکار کرکہتا تھا کہ مکہ اور عرب تو کیا ہے میں قیصر وکسریٰ کی حکومتوںکو بھی مٹادوں گا.اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اس نے کہا تھا ویسا ہی وقوع میں آگیا.اگر یہ باتیں ایسی ہی ظاہر تھیں جیسے آج یورپین مصنّف لکھتے ہیں تو مکہ کے لوگ کیوں کہتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹادیں گے.عرب کے لوگ کیوں کہتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹادیں گے.ان کا بڑے زور سے یہ اعلان کرنا کہ اسلام کو ہم کچل کر رکھ دیں گے بتاتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتے.قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تو کجا مکہ کی بستی والوں کا مقابلہ کرنا بھی ان کی طاقت سے باہر ہے.مگر پھر وہ زمانہ آیا جب وہ اکیلا اور کمزور شخص بڑھا اور بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچا کہ قیصر و کسریٰ بھی اس کے مقابلہ کی تاب نہ لاسکے.یہی حالت اس وقت ہماری ہے.ہم دنیا میں سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ بے سامان ہیں اور کوئی شخص ظاہری سامانوں کے لحاظ سے یہ خیال بھی نہیں کرسکتا کہ ہم کسی دن ساری دنیا پر غالب آجائیں گے.لیکن آج سے دو تین سو سال کے بعد جب احمدیت کا سب جہان پر غلبہ ہوگیا یورپین مصنّفین کی طرح
Page 234
بعض ایسے مصنّف پیدا ہوجائیں گے جو کہیں گے کہ احمدیت نے اگر غلبہ پالیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے.دنیا میں اس وقت حالات ہی ایسے پیدا ہورہے تھے کہ جن کے نتیجہ میں اس نے جیت جانا تھا.یورپ میں تنزّل کے آثار پیدا تھے.ایشیا میں تنزّل کے آثار پیدا تھے اور حکومتوں کی بنیادیں بالکل کھوکھلی ہوچکی تھیں.ایسی حالت میں اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ پیشگوئی شائع کردی کہ ایک زمانہ میں احمدیت سارے جہان پر غالب آجائے گی تو یہ کوئی پیش گوئی نہیں کہلاسکتی.مگر سوال تویہ ہے کہ کیا آج دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو اس دعویٰ کو معقول قرار دے سکے اور کہہ سکے کہ واقعہ میں ایک دن احمدیت کا سب جہان پر غلبہ ہوجائے گا.اگر آج نہیں کہتے تو دو تین سو سال کے بعد غلبہ میسر آنے پر یہ کہنا کہ غلبہ تو ہو ہی جانا تھا اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا.یہ لوگوں کے جھوٹا ہونے کی ایک بیّن علامت ہوتی ہے کہ جب وقت گذرجاتا ہے تو نشاناتِ الٰہیہ پر پردہ ڈالنے کے لئے کئی قسم کے بہانے بنانے لگ جاتے ہیں اور پیش گوئیوں کی وقعت کم کرنے کے لئے یہ کہنا شروع کردیتے ہیں کہ زمانہ کے حالات ہی ایسے تھے جن سے یہ نتیجہ نکلتا.مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو گذرچکا.اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ ہے اور آپ نے بطور پیش گوئی یہ اعلان فرمایا ہے کہ احمدیت کی ترقی کی پیش گوئی ’’اے تمام لوگو سن رکھو کہ یہ اس کی پیش گو ئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا.وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلادے گا اور حجت اور برہان کے رو سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا.وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا.خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی‘‘.( تذکرہ صفحہ ۴۱۰ نیز تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۶۶) مولوی ثناء اللہ صاحب بارہا اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس پیشگوئی پر مدتیں گذرچکی ہیں مگر ابھی تک احمدیت کو غلبہ میسر نہیں آیا.لیکن کچھ عرصہ گذرنے پر جب احمدیت کو دنیا میں کامل غلبہ حاصل ہوگیااس وقت مولوی ثناء اللہ صاحب کے جو چیلے موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو نظر ہی آرہاتھا کہ جماعت احمدیہ نے جیت جانا ہے.اس وقت تنزّل کے آثار یورپ میں پیدا ہوچکے تھے.اس وقت تنزّل کے آثار ہندوئوں میں پیدا ہوچکے تھے.اس وقت تنزّل کے آثار مسلمانوں میں پید اہوچکے تھے اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ احمدیت ان کے مقابلہ میں جیت جاتی.غرض
Page 235
مخالفین کا ہمیشہ سے یہ دستور چلا آیا ہے کہ پہلے تو غلبہ کو ناممکن بتاتے ہیں اور جب غلبہ میسر آجاتا ہے تو کہنا شروع کردیتے ہیں کہ اس میں عجیب بات کوئی نہیں حالات کا تقاضا یہی تھا کہ انہیں غلبہ میسر آجاتا.بہرحال ہر زمانہ میں دنیا، دنیا کے اسباب سے وابستہ ہوتی ہے لیکن زمانۂ نبوت میں اللہ تعالیٰ اسے نبوت کے ساتھ وابستہ کرکے اپنی حکومت ظاہر کرتا ہے.ورنہ دنیوی حکومت کا انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہوتا.وہ خدا کی خدائی ظاہر کرنے کے لئے دنیا میں آتے ہیں اور یہ خدائی ان کے زمانہ میں اس رنگ میں ظاہر ہوتی ہے کہ بغیر مادی اسباب کے ایک گری ہوئی قوم کو وہ اٹھاتے اور اسے دنیا پر غالب کرکے دکھادیتے ہیں.تب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ دنیوی ترقی میں صرف ہماری کوششوں کا دخل نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی حکومت کا بھی دخل ہے.جب تک وہ دخل نہ دے اس وقت تک تو تدابیر کام کرتی رہتی ہیں لیکن جب وہ دخل دے دے تو ساری دنیا بے بس ہوجاتی ہے اور اس کی کوئی تدبیر اسے کامیاب نہیں کرسکتی.اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت دنیوی تدابیر باطل ہوجاتی ہیں.باطل نہیں ہوتیں بلکہ ایمان کے ساتھ مل کر نتیجہ پیدا کرتی ہیں اس کے بغیر نہیں.جیسا کہ اگلی آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیاہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانہ کو عصر کا زمانہ قرار دیا ہے گو ان معنوں کے لحاظ سے نہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں بلکہ اور معنوں کے لحاظ سے.چنانچہ بخاری میں روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے عمارت بنانے کے لئے بہت سے مزدور کام پر لگائے جنہوں نے ظہر تک کام کیا.پھر اس نے ایک اور پارٹی مقرر کی جس نے عصر تک کام کیا.اس کے بعد اس نے ایک تیسری پارٹی مقرر کی جس نے شام تک کام کیا.جب دن ختم ہونے پر اس نے مزدوری تقسیم کی تو سب کو برابر بدلہ دیا.اس پر پہلوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے زیاہ لمبا عرصہ کام کیا تھا مگر ہمیں بھی اتنا ہی بدلہ دیا گیاہے جتنا ان لوگوں کو بدلہ دیا گیا ہے جنہوں نے ظہر سے عصر تک یا عصر سے مغرب تک کام کیا ہے.مالک مکان نے انہیں جواب دیا کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا آیا اس وعدہ کو میں نے پورا کردیا ہے یانہیں.جب میں نے اس وعدہ کو پورا کردیا ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور تمہارا حق مارا نہیں تو تمہیں یہ شکوہ کیوں پیدا ہو کہ میںنے دوسروں کو تھوڑے وقت کی مزدوری پر بھی تمہارے برابر بدلہ دے دیا.اگر میں تمہیں کم مزدوری دیتا تو بے شک تم اعتراض کرسکتے تھے لیکن جب میں نے تمہیں پوری مزدوری دے دی تو اس کے بعد اگر میں نے کسی کو کام سے زیادہ بدلہ دے دیاہے تو اس پر تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں.پھر آپ نے فرمایا پہلی مزدور قوم سے یہودی مراد ہیں، دوسری مزدور قوم سے نصاریٰ مراد ہیں اور تیسری مزدور قوم سے اے مسلمانو تم مرادہو.( صحیح بخاری کتاب الاجارۃ باب الاجارۃ الی نصف النـھار ) اس سے معلوم ہوتاہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
Page 236
نے بھی ایک مفہوم کے لحا ظ سے اپنے زمانہ کو عصر کا زمانہ قرار دیا ہے.عَصْـرٌ کے معنے رَھْطٌ اور عَشِیْـرَۃٌ کے بھی ہوتے ہیں یعنی قبیلہ اور قوم کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس لحاظ سے وَ الْعَصْرِ.اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ کے معنے یہ ہوں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انسان یقیناً گھاٹے کی طرف جا رہا ہے.ان معنوں کے لحاظ سے یہاں انسان سے عام انسان مراد ہے اور قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا تو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے لیکن مکہ والے تمہارے سامنے ہیں.اگر تم اور لوگوںکے حالات کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا مکہ والوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان کی حالت کہاں سے کہاں جاپہنچی ہے.مکہ کے لوگ ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ جیسے پاک انبیاء کی نسل میں سے ہیں.خانہ کعبہ کے پاس رہنے والے ہیں.ان کی طرف دیکھو کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک اچھے خاندان میں سے ہیں اور خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام ان کے سپرد کیا گیا تھا.پھر بھی یہ روز بروز خدا تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جارہے ہیں.بجائے اس کے کہ اپنے فرائض اور ذمہ واریوں کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کریں.یہ لوگ مجاور بن کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کی دن رات یہی کوشش رہتی ہے کہ لات اور منات اور عزّیٰ کو لوگ سجدے کریں اور ان پر چڑھاوے چڑھائیں جس سے ان کا گذارہ ہو.پس وَ الْعَصْرِ کے معنے یہ ہوئے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ قوم اس بات کی مستحق تھی کہ خدا تعالیٰ کے نام کو دنیا میں پھیلاتی مگر یہ قوم بھی مجاور بن کر بیٹھ گئی ہے اور خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کی بجائے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑی ہے.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ ضلالت اور گمراہی اب پورے طور پر مسلط ہوچکی ہے اور ضروری تھا کہ ان حالات کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی مبعوث ہوتا.تیسرے معنے عصر کے رات کے ہیں.ان معنوں کی رو سے ایک عام قاعدہ اس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب قوم پر تباہی کا زمانہ آتا ہے تو اس سے نکلنے کی راہ صرف ایمان و عمل صالح ہی رہ جاتا ہے یعنی بغیر خدائی ہدایت کے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی.یہ امر ظاہر ہے کہ رات کا زمانہ تاریکی کا زمانہ ہوتا ہے.پس اس جگہ وَالْعَصْرِ سے وہ زمانہ مراد ہے جب کسی قوم پر تباہی وارد ہوجاتی ہے اور کامیابی کی کوئی شعاع اسے دکھائی نہیں دیتی.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم رات کے زمانہ کو یعنی تباہی اور بربادی کے زمانہ کو اس بات کی شہادت کے طور پر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیںکہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ.اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جب قوموں پر تنزّل آجاتا ہے تو اس وقت ایسی قومیں جو کسی دینی سلسلہ سے تعلق رکھتی ہیں اس تباہی سے کبھی بچ نہیں سکتیں سوائے اس کے کہ ان
Page 237
کے احیاء کے لئے کوئی نبی آئے اور انہیں اس پرایمان لانے کی سعادت حاصل ہوجائے.یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کے خلاف دنیا میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی.جب بھی کوئی مذہبی جماعت گری ہے ہمیشہ کسی نبی کے ذریعہ ہی اس کا احیاء ہوا ہے اس کے بغیر کسی قوم کا آج تک احیاء نہیں ہوا.مثلاً تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حضرت کرشنؑ آئے اور پھر حضرت رام چندرؑ آئے یا ہندوئوں کے خیال کے مطابق پہلے حضرت رامؑ آئے اور بعد میں حضرت کرشنؑ آئے ان میں سے کوئی صورت سمجھ لو.ہمارے نزدیک پہلے حضرت کرشنؑ کے ذریعہ ہندو قوم کو ترقی حاصل ہوئی اور پھر ایک لمبے عرصہ کے بعدجب ان میں تنزّل پیدا ہوا تو وہ تنزّل اس وقت دور ہوا جب حضرت رامؑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگئے.یا ہندوئوں کے عقیدہ کے مطابق پہلے حضرت رامؑ کے ذریعہ ان کو ترقی ملی اور بعد میں حضرت کرشنؑ نے ان کو عروج تک پہنچایا.اس کے بعد جب پھر ان میں تنزّل پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بدھؑ کو لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرما دیا جن پر ایمان لاکر قوم کاتنزل دور ہوا.بہرحال جب بھی کسی مذہبی جماعت کو تنزّل کے بعد عروج ہوا ہے ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حاصل ہوا ہے.دنیوی تدابیر سے کام لے کر آج تک کوئی ایک مذہبی جماعت بھی کامیابی حاصل نہیں کرسکی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل قانون ہے جس کے خلاف ہمیں کوئی نظارہ نظر نہیں آتا اور کوئی شخص ایسی مثال پیش نہیں کرسکتا کہ فلاں جماعت جس کا مذہب کے ساتھ تعلق تھا ترقی کے بعد گرچکی تھی مگر محض دنیوی تدابیر سے کام لے کر اس نے دوبارہ عروج حاصل کرلیا.مذہبی جماعتوں کے زوال کے بعد ترقی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ وابستہ کردی ہے.جو قوم یہ وابستگی پیدا کرلیتی ہے وہ عروج حاصل کرلیتی ہے اور جو اس وابستگی سے محروم رہتی ہے وہ خواہ لاکھ تدابیر اختیار کرے کبھی اپنے زوال کو دور نہیں کرسکتی.مثلاً یہودیوں کو دیکھ لو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے قوم کو عروج تک پہنچایا.اس کے بعد جب ان میں تنزّل پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے ایک گری ہوئی قوم کو ترقی کے بلند مینار تک پہنچادیا.پھر تنزّل پیدا ہوا تو حضرت شمعونؑ آگئے جنہوں نے قوم کی اصلاح کی پھر تنزّل پیدا ہوا تو حضرت دائودؑ آگئے اور انہوںنے اصلاح کی.غرض ہمیشہ انبیاء کے ذریعہ ہی ان کو ترقی حاصل ہوئی.ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پر ایمان لائے بغیر انہیں محض دنیوی تدابیر سے عروج حاصل ہوگیا ہو.اسی طرح بابل کی حکومت نے ان کو تباہ کردیا تو اللہ تعالیٰ نے عزرا نبی کو کھڑا کردیا جس نے ان کی ذلت دور کی.پھر گرے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا.یہ نہیں ہوا کہ دنیوی لیڈروں کی اتباع کرکے انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہو یا مادی تدابیر نے ان کو ترقی تک پہنچادیا ہو.یہی قانون اب مسلمانوں کے متعلق بھی کام کررہا ہے.مسلمان اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے
Page 238
ہیں کہ ہماری کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم انجمنیںبنائیں، مدرسے جاری کریں، یونیورسٹیاں اور کالج قائم کریں، صنعت و حرفت اور تجارت کی طرف توجہ کریں اور اس طرح اپنی ذلت و نکبت کو دور کرکے ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہوجائیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آ ج تک کوئی ایک مثال بھی تو ایسی نہیں ملتی کہ کسی مذہبی جماعت کو تنزّل کے بعد محض دنیوی تدابیر سے غلبہ حاصل ہوگیا ہو.جب بھی کوئی مذہبی جماعت گری ہے اسے نبی کے ذریعہ ہی دوبارہ عروج حاصل ہوا ہے.اس کے بغیر عروج حاصل ہونے کی کوئی ایک مثال بھی تاریخ سے پیش نہیں کی جاسکتی.بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے تو انگلستان کیوں ترقی کرگیا یا امریکہ کیوں ترقی کرگیا.یہ لوگ کس نبی پرایمان لائے تھے کہ انہیں ساری دنیا پر غلبہ حاصل ہوگیا.اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو یہ بات ہی غلط ہے کہ انگلستان اور امریکہ وغیرہ نے تنزّل کے بعد ترقی کی ہے.ان قوموں میں سے سوائے جاپان کے اور کوئی قوم ایسی نہیں جس نے ترقی کے مقام سے گرنے کے بعد دوبارہ عروج حاصل کیا ہو.ان کے متعلق یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے وحشیانہ حالت سے ترقی کرتے کرتے عروج حاصل کرلیا.مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایک دفعہ ترقی حاصل کرنے کے بعد جب یہ لوگ بالکل گر گئے تھے تو دوبارہ اپنی تدابیر سے انہوں نے ساری دنیاپر غلبہ حاصل کرلیا.میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی مذہبی جماعت (یعنی جو سچے مذہب کی طرف منسوب ہو) جو ایک دفعہ ترقی حاصل کرنے کے بعد گرجائے وہ اس وقت تک کبھی ترقی نہیں کرسکتی جب تک کوئی نبی اس کی طرف مبعوث نہ ہو.مگر یہ قومیں تو وہ ہیں جو ترقی حاصل کرنے کے بعد ابھی گری نہیں.انہوںنے بے شک ادنیٰ حالت سے ترقی کرتے کرتے یہ مقام حاصل کیا ہے مگر یہ نہیں ہوا کہ تنزّل کے بعد انہوں نے دوبارہ ترقی کی ہو.صرف جاپان کی مثال اس سوال میں پیش کی جاسکتی ہے مگر وہ بھی یہاں چسپاںنہیں ہوتی.اس لئے کہ اگر کوئی قوم خالص دنیوی ذرائع سے کام لے کر ترقی کرجاتی ہے تو وہ وہی قوم ہوتی ہے جس میں نورِ الہام بند ہوچکا ہوتاہے.جب تک کوئی قوم نورِ الہام سے دور نہیں ہوتی اور وہ کسی سچے نبی کو جس کا زمانہ نبوت جاری ہوتا ہے مان رہی ہوتی ہے اس وقت تک وہ قوم کبھی دوبارہ ترقی نہیں کرسکتی جب تک کسی مامور کے ذریعہ سے اسے ترقی نہ ملے.چونکہ آج کل مسلمانوں کے سوا باقی تمام اقوام زندہ دین سے دور ہوچکی ہیں اس لئے ہندو اگر خالص دنیوی تدابیر سے کام لے کر ترقی کرلیں تو وہ کرسکتے ہیں کیونکہ وہ سچے دین کی طرف منسوب نہیں.جب وہ ایک سچے دین کی طرف منسوب تھے اور جب تک ہندو مذہب زندہ تھا پہلے کرشنؑ آئے جن پر ایمان لاکر انہیں ترقی حاصل ہوئی.پھر رامؑ آئے جن پر ایمان لاکر انہیں ترقی حاصل ہوئی.پھر بدھؑ آئے جن پر ایمان لاکر انہیں ترقی حاصل ہوئی یا ہندوئوں کے نزدیک پہلے رامؑ پھر کرشنؑ
Page 239
اور پھر بدھؑ آئے اور ان کے ذریعہ انہیں ترقی حاصل ہوئی.لیکن بدھؑ کے بعد چونکہ ہندو مذہب اور پھر بدھ مذہب منسوخ ہوگیا اس لئے اب اگر ہندو محض دنیوی تدابیر سے ترقی کرجائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں.لیکن مسلمان کبھی دنیوی تدابیر سے ترقی نہیں کرسکتے.کیونکہ مسلمان ایک سچے مذہب کوماننے والے ہیں اور جس جماعت کی یہ حالت ہو وہ تنزّل کے بعد بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی بعثت کے دوبارہ ترقی نہیں کیا کرتی.عیسائی اگر تنزّل کے بعد ترقی کرجائیں تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ عیسائیوں سے اب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے تمام تعلقات منقطع کرچکا ہے اور ان کا مذہب منسوخ ہوچکا ہے.پس یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کہ دنیا کی ترقی دین کے ساتھ وابستہ ہے ہر قوم کے متعلق نہیں بلکہ ان اقوام کے متعلق ہے جو ابھی اللہ تعالیٰ کے الہام سے محروم نہیں ہوئیں.اگر ان کو بھی دین کے بغیر دنیا میں ترقی مل جائے تو پھر دین کا کسی قوم کے پاس بھی حصہ نہ رہے اور خدا تعالیٰ کا خانہ بالکل خالی ہوجائے.اس لئے اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں کو کبھی ترقی نہیں دے سکتا جب تک وہ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرلیتے.آج اللہ تعالیٰ کنفیوشس مذہب کے پیروئوں کو بالکل چھوڑ بیٹھا ہے، زرتشتی مذہب کے پیروئوں کو بالکل چھوڑ بیٹھا ہے، بدھ مذہب کے پیروئوں کو بالکل چھوڑ بیٹھا ہے، ہندومذہب کے پیروئوں کو بالکل چھوڑ بیٹھا ہے، عیسائی مذہب کے پیروئوں کو بالکل چھوڑ بیٹھا ہے اور ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی زمیندار کا بیل بڈھا ہوجائے تو وہ اسے کھلا چھوڑ دیتا ہے اور اس بات کی پروا تک نہیں کرتا کہ وہ رات کو گھر میں واپس آتا ہے یا نہیں.لیکن مسلمانوں کی مثا ل دودھ دینے والی گائے کی سی ہے.ایک بڈھا بیل جسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے متعلق مالک کا اور قانون ہوتا ہے اور گھر کی دودھ دینے والی گائے کے متعلق مالک کا اور قانون ہوتا ہے.بوڑھا بیل اگر رات کو گھر میں نہیں آتا تو مالک اس کی پروا بھی نہیں کرتا.لیکن اگر دودھیلی گائے رات کو گھر میں نہ آئے تو وہ ادھر ادھر دوڑا پھرتا ہے اور ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ میری گائے کدھر گئی.پس وہ جماعتیں جن کا خدا تعالیٰ سے تعلق کٹ چکا ہوتا ہے اگر دنیوی تدابیر سے ترقی کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پروا نہیں ہوتی لیکن وہ جماعتیں جن کا خدا تعالیٰ سے روحانی تعلق باقی ہوتا ہے ان کے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ان کی اصلاح اور ترقی بغیر نبی کے نہیں ہوتی.پس انگلستان اور امریکہ اور جاپان وغیرہ کی مثالیں یہاں چسپاں نہیں ہوتیں.یہ قانون ان اقوام کے متعلق ہے جن کا بھی خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق ہوتا ہے نہ ان کے متعلق جو خدا تعالیٰ سے بغاوت اختیار کرکے نورِ الہام سے کلیۃً محروم ہوجاتی ہیں.
Page 240
چوتھے معنے اس کے یہ ہیں کہ دن کو ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے.اس سے اس قاعدہ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب شمس رسالت کا طلوع ہوتا ہے تو کوئی قوم جو اس کے مقابل پر ہو بغیر اس پر ایمان لانے کے تباہی سے بچ نہیں سکتی.پانچویں معنے اس کے یہ ہیں کہ ہم عطیہ کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں.یعنی جب اللہ تعالیٰ دنیا پر احسان کرتا اور نبوت اور کلام بھیجتا ہے تو صرف مومن ہی ترقی کرسکتے ہیں دوسرے لوگ ترقیا ت سے محروم رہ جاتے ہیں.خُسْـرٌ کے معنے جیسا کہ اوپر بتایا جاچکا ہے عربی زبان میں گھاٹے کے بھی ہیں، گمراہی کے بھی ہیں اور ہلاکت اور بربادی کے بھی ہیں.ان تینوں میں سے ہلاکت کے معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر اس آیت کو اسلام کے آخری زمانہ پر چسپاں کیا جائے تو اَلْاِنْسَان سے مراد ’’مردِ مغرب‘‘ ہوگا اور اس میں یہ پیش گوئی پائی جائے گی کہ مغربی لوگ صرف اپنے آپ کو انسان سمجھیں گے باقی دنیا میںسے کسی کو بھی انسان سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوںگے اور لَفِيْ خُسْرٍ کا مفہوم یہ ہوگا کہ جتنا جتنا وہ اپنے آپ کو کامل انسان بنائیں گے اتنا ہی ان کی ہلاکت کا سامان پیدا ہوتا چلا جائے گا.چنانچہ اب یہ حقیقت تمام دنیا پر منکشف ہورہی ہے کہ جس قدر تہذیب ترقی کررہی ہے اسی قدر تباہی اور بربادی کے سامان بھی بڑھتے چلے جارہے ہیں.انہی سامانوں میں سے ایک ایٹم بم ہے جو اس جنگ میں ایجاد کیا گیا.یہ ایک ایسا خطرناک اور تباہ کن ہتھیار ہے کہ جنرل میکارتھر نے اپنے ایک اعلان میں صاف طور پر کہا ہے کہ یا تو ہمیں اسلحہ کی اس ترقی کے مقابلہ میں اپنے اخلاق میں بھی نمایاں ترقی کرنی پڑے گی ورنہ اگر اخلاق میں ترقی نہ ہوئی تو دنیا کی تباہی میں کوئی شبہ نہیں.یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جگہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جتنا جتنا اپنے آپ کو اَلْاِنْسَان قرار دیں گے اوریہ دعویٰ کریں گے کہ ہم میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے حساب دان ہیں، بڑے بڑے ماہرین تجارت ہیں، بڑے بڑے صناع ہیں، بڑے بڑے موجد ہیں اتنا ہی وہ ہلاکت کے قریب ہوتے جائیںگے اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودیں گے.اسی طرح خُسـر کے معنے ضلالت کے بھی ہیں.اس لحاظ سے آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ آخری زمانہ میں لوگ مومنوں کو ذلیل اور ادنیٰ سمجھیں گے اور اپنے آپ کو ہی انسان سمجھیں گے لیکن ہدایت صرف مومنوں کے پاس ہوگی.اس وقت ایک موعود کا پیدا ہونا اور عصر کامل یعنی نبی کا وجود اس امر کا ثبوت ہوگا کہ بظاہر کامل نظر آنے والا انسان گمراہی میں مبتلا ہے یعنی دنیا پر مغربی لوگوں کی غلطی ثابت کرنے کا ذریعہ صرف نبی کا وجود ہوگا.ورنہ اور کوئی صورت نہ ہوگی کہ ان کی گمراہی ثابت کی جا سکے صرف روحانی طور پر ہی یہ امر ثابت ہوسکے گا.اس صورت میں
Page 241
لْعَصْـر سے مراد کامل عصر ہوگا اور کامل عصر وہی ہوتا ہے جس میں خدا تعالیٰ کا کوئی نبی لوگوں کی ہدایت کے لئے معبوث ہو.پس فرماتا ہے اس وقت ایک قوم کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ہی انسان سمجھے گی کسی اور کوانسان قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہوگی مگر ہوگی گمراہ.اور اس کی گمراہی کے ثابت ہونے کا دنیا کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا صرف روحانی طور پر یہ امر ثابت ہوسکے گا.چنانچہ دیکھ لو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃوالسلام کی بعثت کے بعد مغربی لوگوں کی گمراہی ثابت کرنا کون سا مشکل کام رہ گیا ہے ہم میں سے ہر شخص علی الاعلان کہہ سکتا ہے کہ اہل مغرب گمراہ ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا ایک نبی آیا جسے ہم نے تو مان لیا مگر مغرب اس کا منکر ہے اس لئے ہم ہدایت پر ہیں اور وہ گمراہی پر.مگر باقی مذاہب کس ذریعہ سے یورپ پر اپنی برتری ثابت کر سکتے ہیں.وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم مغرب پر فوقیت رکھتے ہیں یا ہمارے پاس تو ہدایت ہے لیکن مغرب کے پاس ہدایت نہیں.وہ حیران و پریشان کھڑے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے وہ یورپ کی گمراہی ثابت کرسکیں.اسلام زندہ باد یا غیرمذاہب مردہ باد کے فلک شگاف نعرے بلند کرنا کوئی مشکل امر نہیں جو شخص چاہے یہ نعرے بلند کرسکتا ہے.مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے دلوں پر بھی اسلام کا اثر ہے یا محض زبان تک ان کے دعوے محدود ہیں؟ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے حالات پر گہرا غور کرے تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج مسلمانوں پر اسلام کاکچھ بھی اثر نہیں.وہ بظاہر اسلام زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں مگر چلتے یورپ کے پیچھے ہی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم تو ہمیں تباہی سے نہیں بچا سکتی لیکن یورپ کی تقلید ہمیں بچاسکتی ہے.اگر اس حصہ کو الگ کرلیا جائے جو سیاسی جدوجہد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور یہ دیکھا جائے کہ سیاسی رنگ میں یورپ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ایک مسلمان کیا بننا چاہتا ہے تو صاف طور پر دکھائی دیتا ہے کہ یورپ کی سیاسی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد ایک مسلمان انگلستان کا چرچل تو بننا چاہتا ہے مگر وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں عرب کا ابوبکرؓ بن جائوں.وہ یہ تو خواہش رکھتا ہے کہ میری گردن مغرب کے سیاسی دبائو سے آزاد ہوجائے مگر اس آزادی کے بعد اس کا مقصد ابوبکرؓ بننا نہیں یا عمرؓ اور عثمانؓ بننا نہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں آزادی کے بعد انگلستان کا ایٹلی بنوں یا امریکہ کا ٹرومین بن جائوں یا روس کاسٹالن بن جائوں.اس کی آنکھوں کے سامنے یورپین ممالک کی بااقتدار شخصیتیں یکے بعد دیگرے آتی ہیں اور وہ ایک سردآہ کھینچ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے موقع ملے تو میں بھی مغرب کی طرح دنیا پر حکمرانی کروں.مگر یہ بات کہ میںجلال الدین سیوطیؒ بن جائوں یا امام بخاریؓبن جائوں یا سیّد عبدالقادر جیلانیؓ بن جائوں کبھی وسوسہ کے طور پر بھی کسی مسلمان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی.پس فرماتا ہے اس وقت کوئی جماعت ایسی نہیں ہوگی جو مردِ مغرب کو گمراہی پر سمجھنے والی ہو.ہر قوم
Page 242
اس کی نقل کرنا چاہے گی اور اس کی تقلید پر ہی اپنی تمام کامیابی کا دارومدار سمجھے گی.سیاسی آزادی بالکل الگ چیز ہے اس آزادی کے معنے صرف اتنے ہی ہیں کہ ہم کو بھی ویسی ہی برتری مل جائے جیسے مغرب کو حاصل ہے.ورنہ اس سیاسی آزادی کے بعد ہر قوم کے دل میں خواہش یہی پائی جاتی ہے کہ مجھے بھی مغرب کی طرح اقتدار حاصل ہو.بہرحال اس وقت کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی جو مغربی لوگوں کی گمراہی ثابت کرسکے صرف نبی کا وجود ہوگا جس پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک جماعت نہایت اطمینان کے ساتھ یہ کہے گی کہ یورپ کے لوگ کہاں جیت سکتے ہیں.جیتنا تو ہم نے ہے جو ایک نبی پر ایمان لائے ہیں.گویا امید جو جیتنے کا ایک ہی ذریعہ ہوتا ہے صرف مومنوں کو نصیب ہوگا.دوسری اقوام جو نہ مومن ہوں گی اور نہ مردِ مغرب کی ساتھی وہ حیران و پریشان ہوں گی.نہ مردِ مغرب ان کو اپنے ساتھ شامل کرے گا اور نہ اس کی کمزوری اور گمراہی انہیں نظر آسکے گی.اس لئے وہ سرگردان و حیران ہوں گی.امیدکا کوئی پہلو انہیں نظر نہ آتا ہوگا.یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر یورپ کے سامنے ہمیں اپالوجی APOLOGY کرتے دکھائی دیتے ہیں.ان میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھلے اور واضح الفاظ میں مغرب کی برائی اس پر ظاہر کرسکیں.سید امیر علی صاحب نے اپنی کتب میں یورپین مصنفین کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے مگر انہوں نے سب جگہ اپالوجی سے کام لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یورپین مصنفین کے اسلام کے خلاف اعتراضات درست ہیں مگر ہماری التجا صرف اس قدر ہے کہ اسلام کے متعلق زیادہ سخت رائے قائم نہ کی جائے کیونکہ اسلام ایسے زمانہ میں آیا تھا جب دنیا ابھی ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے تھی.اس لئے اس کے کئی مسائل موجودہ زمانہ کی ضروریات کے لئے مکتفی نہیں ہوسکتے.لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپالوجی کو بالکل ردّ کرتے ہوئے کھلے الفاظ میں یورپین لوگوں پر ان کی گمراہی ثابت کی ہے اور بتایا ہے کہ اسلام نے جو کچھ کہا اس کا ایک ایک حرف درست ہے.اس پر اعتراض کرنا خود اپنی حماقت کا ثبوت بہم پہنچانا ہے.چنانچہ آج تک ہم دشمنوں کی طرف سے اسی وجہ سے گالیاں کھاتے ہیں کہ ہم نے آریوں پر بھی اعتراضات کئے.ہم نے ہندوئوں پر بھی اعتراضات کئے.ہم نے سکھوں پر بھی اعتراضات کئے.ہم نے عیسائیوں پر بھی اعتراضات کئے.ہم نے جینیوں اور بدھوں پر بھی اعتراضات کئے.ہم نے زرتشتیوں پر بھی اعتراضات کئے.ہم نے یہودیوں پر بھی اعتراضات کئے.غرض کوئی مذہب اور فرقہ ایسا نہیں جس کی اسلام کے مقابلہ میں ہماری طرف سے گمراہی ثابت نہ کی گئی ہو اور ہم نے ان پر ایسے وزنی اعتراضات نہ کئے ہوں کہ جن کا جواب دینا ان کے لئے بالکل ناممکن ہے.مگر بجائے اس کے کہ مسلمان ہمارے اس کام کی قدر کرتے انہوں نے الٹا ہمیں گالیاں دینا شروع کردیا
Page 243
اور کہنے لگے کہ ہم اسلام کے خلاف غیرمسلموں کو اشتعال دلارہے ہیں.چنانچہ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے مظہر علی صاحب اظہر کا ایک رسالہ میں نے دیکھا جس میں انہوں نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ آریوں نے اگر اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مرزا صاحب نے آریوں پر اعتراضات کرنے شروع کردیئے تھے.اگر وہ اعتراضات نہ کرتے تو آریہ بھی اسلام کی مخالفت نہ کرتے.گویا دوسرے الفاظ میں مظہرعلی صاحب اظہر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو دشمن کے مقابلہ میں اپالوجی کرنی چاہیے تھی.بجائے اس کے کہ اس کے اعتراضات کے جواب دیتے کہتے کہ خدا کے واسطے آپ ہم پر سختی نہ کریں.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ایک جاہل امت کے سردار تھے وہ موجودہ زمانہ کے مسائل کو کہا ں سمجھ سکتے تھے یا قرآن کریم کی تعلیم نعوذ باللہ موجودہ زمانہ میں کام نہیں آسکتی.یہ تو صرف عرب کے لئے مخصوص تھی.موجودہ زمانہ میں مغربی علوم ہی لوگوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچاسکتے ہیں.مگر چونکہ مرزا صاحب نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوںنے کھلے طور پر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں.قرآن کریم کی تعلیم دنیا کی تمام تعلیموں سے اعلیٰ ہے.جاہل اور احمق وہ لوگ ہیں جو آپ پر اعتراضات کرتے اور قرآنی تعلیم کی حقیقت کو نہیں سمجھتے.اس لئے بقول مظہرعلی صاحب آریوں کو جوش آگیا اور وہ اسلام کا مقابلہ کرنے لگ گئے.اگر مرزا صاحب ایسا نہ کرتے تو ان کو بھی مقابلہ کا جوش پیدا نہ ہوتا.غرض سب مسلمانوں کے دلوں میں آج امید بالکل مٹ چکی ہے.صرف ہماری جماعت ایسی ہے جو اپنے اندر ایک پُر امید دل رکھتے ہوئے مغرب کی گمراہی ثابت کررہی ہے اور یقین رکھتی ہے کہ مغرب اس کے مقابلہ میں کبھی جیت نہیں سکتا.پس وَ الْعَصْرِ.اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ کے معنے یہ ہوئے کہ ہم اَلْعَصْـر یعنی زمانۂ نبوت کو اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں باقی ساری قومیں یورپ کے دبدبہ اور اس کی شوکت و حشمت سے مرعوب ہوجائیں گی اور وہ سمجھیں گی کہ دنیا کی نجات صرف مغرب کی تقلید میں ہے.لیکن ایک جماعت جو ایمان اور عمل صالحہ کی دولت سے مشرف ہوگی اس کے افراد اس خیال کوباطل قرار دیں گے.وہ کہیں گے کہ یورپ ہمارے مقابلہ میں کہاں جیت سکتا ہے اس نے تو یقیناً تبا ہ ہوجانا ہے.باقی قومیں چونکہ صرف دنیوی نقطۂ نگاہ سے مغرب کو دیکھیں گی اس لئے یورپ کا مرد انہیں مردِ کامل نظر آئے گا.لیکن وہ لوگ جو یورپ کو روحانی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے انہیں یورپ کا مرد ’’مردِ بیمار‘‘ نظر آئے گا.چنانچہ آج بالکل یہی کیفیت رونما ہے.آج یورپ کے لوگوں کو ٹرکی مردِ بیمار نظر آتا ہے اور ایشیائی ممالک کو یورپ مردِ توانا دکھائی دیتا ہے لیکن
Page 244
جماعت احمدیہ کے افراد کو باقی تمام دنیا کے خلاف یورپ مردِ بیمار نظر آتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مردِ بیمارکبھی ہم پر غلبہ حاصل نہیں کرسکتا.اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مگر وہ لوگ جو (انبیاء پر) ایمان لے آئے اور (پھر) انہوں نے (موقعہ کے) مناسب عمل کئے وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ١ۙ۬ اور (اصول) صداقت پر قائم رہنے کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِؒ۰۰۳ اور (مشکلات پیش آمدہ پر) صبر (سے کام لینے ) کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے رہے (ایسے لوگ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں ہوسکتے).حلّ لُغات.صَالِـحَات صَلَحَ سے ہے اور صَلَحَ الشَّیْءُ (صَلَاحًا وَصُلُوْحًا وَصَلَاحِیَّۃً) ضِــدُّ فَسَدَ اَوْ زَالَ عَنْہُ الْفَسَادُ.یعنی صَلَحَ الشَّیْءُ کے معنے ہوتے ہیں چیز درست ہوگئی یا اس میں جو خرابی پائی جاتی تھی وہ دور ہوگئی اور اَلصَّالِـحُ کے معنے ہوتے ہیں اَلْقَائِمُ بِـمَا عَلَیْہِ مِنْ حُقُوْقِ الْعِبَادِ وَ حُقُوْقِ اللہِ تَعَالٰی ایسا شخص جو ان تمام حقوق کو ادا کرے جو خدا اور اس کے بندوں کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں.اسی طرح کہتے ہیں ھُوَ صَالِـحٌ لِّکَذَا اَیْ لَہٗ اَھْلِیَّۃُ الْقِیَامِ بِہٖ یعنی جب ھُوَ صَالِـحٌ لِّکَذَا کہا جائے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص میں کام کو کما حقہ ٗ سرانجام دینے کی اہلیت پائی جاتی ہے(اقرب).پس اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کے معنے یہ ہوئے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایسے عمل کئے جو فساد و خرابی سے پاک ہیں یا موقعہ کے مناسب ہیں یا جن سے حقوق اللہ و حقوق العباد ادا ہوجاتے ہیں.تَوَاصَوْا.تَوَاصَوْا تَوَاصَی سے جمع کا صیغہ ہے اور تَوَاصَی الْقَوْمُ کے معنے ہوتے ہیں وَصّٰی بَعْضُھُمْ بَعْضًا قوم کے افراد نے ایک دوسرے کو تاکید کی (اقرب).پس تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے معنے یہ ہوئے کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں.اَلْـحَقُّ: ضِدُّ الْبَاطِلِ حق کے معنے ایسی بات کے ہیں جو جھوٹ کے خلاف ہو.اور حق کے معنے اَلْاَمْرُ الْمَقْضِیُّ
Page 245
کے بھی ہیں یعنی ایسا امر جو وقت اورحالات کے مطابق ہو اور حق کے معنے عدل کے بھی ہیں اور حق کے معنے مال کے بھی ہیں اور حق کے معنے بادشاہت کے بھی ہیں اور حق کا لفظ اَلموْجُوْدُ الثَّابِتُ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.یعنی وہ چیز جو حقیقی وجود رکھتی ہو اور دنیا میں قائم رہنے والی ہو.اور حق کے معنے اَلْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ کے بھی ہیں یعنی شک کے بعد اگر کسی شخص کے دل میں یقین پید اہوجائے تو اس کو بھی حق کہا جاتا ہے.اور حق کے معنے موت کے بھی ہیں.اور حق کے معنے حزم اور احتیاط کے بھی ہیں اور حق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے(اقرب).اَلصَّبْـرُ.اَلصَّبْـرُ: تَرْکُ الشِّکْوٰی مِنَ الْبَلْوٰی لِغَیْـرِ اللہِ لَا اِلَی اللہِ یعنی صبر مصیبت کے وقت شکایت کو چھوڑ دینے کا نام ہے.لیکن یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کے مفہوم میں صرف اتنی بات شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے پاس شکوہ نہ کرے.اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص اپنی شکایات بیان کرتا ہے تو یہ بات صبر کے خلاف نہیں.چنانچہ لغت میں لکھا ہے فَاِذَا دَعَا اللہَ الْعَبْدُ فِیْ کَشْفِ الضُّـرِّ عَنْہُ لَا یُقْدَحُ یعنی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اسے کہے کہ اے میرے رب میری فلاں مصیبت کو دور کردے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے صبر کے خلاف حرکت کی(اقرب).وَفِی الْکُلِّیَّاتِ اَلصَّبْـرُ فِی الْمُصِیْبَۃِ.ابوالبقا جو ایک بہت بڑے ادیب گذرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کلیات میں لکھا ہے کہ صبر کا لفظ جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دوسروں سے کہا جاتا ہے کہ صبر کرو.یہ صرف مصیبت کے وقت استعمال ہوتا ہے.جب کسی حادثہ کے وارد ہونے پر دوسرے شخص سے کہا جائے کہ آپ صبر سے کام لیں تو اس کے معنے صرف اتنے ہوتے ہیں کہ آپ جزع فزع نہ کریں یا اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کریںیا آہ و فغاں سے اپنی آواز بلند نہ کریں.وَ اَمَّا فِی الْمُحَارَبَۃِ فَشَجَاعَۃٌ.لیکن کبھی لڑائی کے لئے بھی صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے.اس وقت اس کے معنے شجاعت اور بہادری کے ہوتے ہیں.وَ فِی اِمْسَاکِ النَّفْسِ عَنِ الْفُضُوْلِ فَقَنَاعَۃٌ وَعِفَّۃٌ.اسی طرح صبر کا لفظ کبھی اِمْسَاکُ النَّفْس کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.یعنی اگر انسان اپنے نفس کو لغو اور فضول کاموں میں مبتلا ہونے سے روکے تو اس وقت بھی صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن ا س کی دو قسمیں ہیں.اگر مال کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا جائے اور مراد یہ ہو کہ دوسرے نے بے جا طور پر اپنا مال صرف کرنے سے اجتناب کیا ہے تو ایسی صورت میں صبر کے معنے قناعت کے ہوں گے اور جب یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص بڑا صابر ہے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ وہ بڑا قانع ہے.اپنے مال کی حفاظت کرتا اور اسے بے جا طور پر صرف نہیں کرتا.لیکن جب اخلاق کے متعلق یہ لفظ بولا جائے اور کہا
Page 246
جائے کہ فلاں شخص اپنے نفس کو روک کر رکھتا ہے تو اس کے معنے عفت اور پاکیزگی کے ہوں گے وَفِیْ اِمْسَاکِ کَلَامِ الضَّمِیْـرِ کِتْـمَانٌ (اقرب).اسی طرح کبھی صبر کا لفظ اپنے دل کی بات کو ظاہر نہ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.غرض اس لفظ کے کئی معنے ہیں.صبر کے معنے جرأت اور بہادری کے بھی ہیں.صبر کے معنے قناعت کے بھی ہیں.صبر کے معنے عفت کے بھی ہیں اور صبر کے معنے رازداری کے بھی ہیں.تفسیر.عمل صالح اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کے متعلق ایک نہایت اہم نکتہ بیان کیا ہے جسے نظر انداز کرنے کی وجہ سے بسا اوقات لوگوں کو کئی قسم کی ٹھوکریں لگ جاتی ہیں.دنیا میں عام طور پر یہ طریق ہے کہ لوگ بعض اعمال کو اچھا اور بعض کو برا قراردے دیتے ہیں اورپھر کوشش کرتے ہیں کہ جو اعمال ان کے نزدیک اچھے ہیں ان کو اختیار کریں اور جو اعمال ان کے نزدیک برے ہیں ان سے اجتناب کریں.جن اعمال کو وہ اچھا سمجھتے ہیں ان کو اعمال صالحہ قرار دیتے ہیں اور جن اعمال کو وہ برا سمجھتے ہیں ان کو اعمال سیئہ کہتے ہیں.حالانکہ عمل صالح کسی مخصوص عمل کا نام نہیں بلکہ ہر ایسا عمل جو مناسب حال ہو اور جو انسان کی روحانی یا جسمانی ضرورت کے مطابق ہو اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے.یہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس نے ان اعمال کے متعلق جو دین کے مطابق ہوتے ہیں ایک ایسی اصطلاح رکھی ہے جو اپنی ذات میں کامل ہے اور جس میں اس حقیقت کو واضح کردیا گیا ہے کہ کس عمل کو تم اچھا کہہ سکتے ہو اور کس کو برا.باقی مذاہب بنی نوع انسان کو صرف اتنی تعلیم دیتے ہیں کہ تم اچھے اعمال بجالائو لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اچھے اعمال کی تعریف کیا ہے.اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اچھے اعمال بتائو تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، غریبوں کی خدمت کرنا اچھا عمل ہے، صدقہ و خیرات دینا اچھا عمل ہے.حالانکہ یہ مکمل جواب نہیں.اسلام صرف نماز کو عمل صالح قرار نہیں دیتا، اسلام صرف روزہ اور زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کو عمل صالح قرار نہیں دیتا بلکہ اسلام کے نزدیک عمل صالح وہ عمل ہے جو مناسب حال ہو اور انسان کی روحانی یا جسمانی ضروریات کے مطابق ہو.مثلاً روزہ رکھناکتنی بڑی نیکی ہے مگر روزہ رکھنا بھی کبھی اچھا ہوجاتا ہے اور کبھی برا.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کے دن روزہ رکھتا ہے وہ شیطان ہے.اگر روزہ رکھنا ہر حالت میں عمل صالح ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ عید کے دن روزہ رکھنے والا شیطان ہوتا ہے.اس سے معلوم ہوا کہ روزہ اپنی ذات میں اچھا نہیں بلکہ اس وقت اچھا ہے جب خدا تعالیٰ کا حکم اس کے متعلق موجود ہو.اسی طرح نماز بڑی اچھی چیز ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے جب سورج اس کے سر پر ہو یا سورج کے طلوع اور اس کے غروب
Page 247
ہوتے وقت نماز پڑھتا ہے وہ شیطان ہے(مسند احـمد بن حنبل مسند الانصار حدیث ابی عـمامہ الباھلی).اگر نماز اپنی ذات میں عمل صالح ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوعِ آفتاب یا غروبِ آفتاب کے وقت نماز پڑھنے والے کو گناہ گار کیوں قرار دیتے یا اس وقت جب سورج سر پر ہو جو شخص نماز پڑھے اسے شیطان کیوں قرار دیتے.مگر یہ تو ایسے احکام ہیں جن کی حکمتیں سب کو معلوم نہیں ہوتیں.اتنی بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نبی دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہو.دشمن اپنے پورے زور سے حملہ کررہا ہو اور وہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے دشمن کے حملہ کے دفاع میں مشغول ہوں تو ایسی حالت میں اگر کوئی شخص میدان جہاد کو چھوڑ کر ایک طرف مصلّٰی بچھا کر نماز شروع کردے تو ہر شخص اسے دیکھ کر کہے گا کہ وہ شیطان ہے.اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص کتنا بڑانیک ہے مصلّٰی بچھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کررہا اور اس سے رو رو کردعائیںکررہا ہے.بلکہ جو شخص بھی اسے دیکھے گا اسے منافق اور غدار قرار دے گا اورکہے گا کہ جو شخص جہاد کو چھوڑ کر ایک کونہ میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کررہا ہے اور اسے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ دشمن کا حملہ کتنا شدید ہے یا مسلمانوں کو اس وقت کتنے بڑے مصائب کا سامنا ہے.وہ نمازی نہیں بلکہ اسلام کا دشمن اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے.اسی طرح روزہ بڑی اچھی چیز ہے مگر ایک دفعہ جبکہ ایک جہاد کے موقعہ پر بعض صحابہؓ نے روزے نہ رکھے اور بعض نے رکھ لئے.جنہوں نے روزے رکھے تھے وہ میدان میں پہنچ کر نڈھال ہوکر گرگئے اور جن کے روزے نہیں تھے وہ بڑی پھرتی سے جہاد کی تیاری کرنے لگ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھ کر فرمایا آج روزہ داروں سے بے روز بڑھ گئے (النسائی کتاب الصیام باب فضل الافطار فی السفر علی الصوم ).اگر روزہ ہر حالت میں عمل صالح ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ آج روزہ داروں سے بے روز بڑھ گئے.آپ کا روزہ داروں پر غیرروزہ داروں کو ترجیح دینا صاف بتاتا ہے کہ روزہ رکھنا بھی بعض حالات میں عمل صالح ہوتا ہے اوربعض حالات میں عمل غیرصالح.چونکہ جہاد میں طاقت اور ہمت کی ضرورت تھی اس لئے جن لوگوں نے اس دن روزہ نہ رکھا ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ داروں سے زیادہ قابل تعریف سمجھا.غرض عمل صالح کے معنے ایسے عمل کے ہوتے ہیں جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہو.اگر ان حقوق کو ملحوظ نہ رکھا جائے توکوئی عمل عملِ صالح نہیں کہلاسکتا خواہ بظاہر وہ کتنا اچھا نظر آتا ہو.دراصل اسلام یہ نظریہ پیش کرتا ہے کہ خالی عمل کوئی عمل نہیں بلکہ ہمیشہ کسی عمل کی خوبی یا اس کی برائی نسبتی طور پر دیکھی جاتی ہے.بسا اوقات ایک عمل ایک وقت میں اچھا ہوتا ہے لیکن دوسرے وقت میں برا ہوجاتا ہے.پس اس آیت میں عمل صالح کے معنی محض اچھے کام کے نہیں بلکہ ایسے کام کے ہیں جو نسبتی
Page 248
لحاظ سے بھی اچھا ہو.اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر عمل جو تم کو اچھا نظر آتا ہو وہ کرو.بلکہ اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ تم وہ کام کرو جو وقت کے لحاظ سے بھی مناسب ہو کیونکہ ہر عمل خواہ بظاہر کتنا اچھا نظر آتا ہو ایک دوسرے وقت میں برا بن جاتا ہے.مثلاً رحم کا مادہ ہے جب کسی شخص سے پوچھا جائے کہ بتائورحم کیسی چیز ہے وہ فوراً کہہ دے گاکہ رحم سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہوسکتی ہے یہ تو بڑی نیکی ہے.حالانکہ انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے بھی آجاتے ہیں جب رحم ایک خطرناک جرم بن جاتا ہے.مثلاً اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے کسی چور کو سیندھ لگاتا دیکھے اور وہ خیال کرلے کہ مجھے اس پر رحم کرنا چاہیے اگر میں نے پولیس میں اطلاع دی یا اس کو خود ہی گرفتار کرلیا تو اس پر مقدمہ چلے گا اور یہ کئی سالوں کے لئے قید ہو جائے گا.اس کے بیوی بچے الگ پریشان ہوں گے او ریہ علیحدہ مصیبت میں مبتلا ہوگا.تو کوئی شخص اس فعل پر اس کی تعریف نہیں کرے گا.ہر شخص جو اس واقعہ کو سنے گا کہے گا کہ اس نے سخت برا کام کیا اسے چاہیے تھا کہ چور کو فوراً گرفتار کرلیتا.اس کا رحم سے کام لینا اور چور کو گرفتار نہ کرنا خوبی نہیں بلکہ انتہا درجہ کا نقص اور عیب تھا.اب دیکھو رحم ایک وقت اچھی چیزوں میں شمار ہوتا ہے دوسرے وقت بری چیز بن جاتا ہے اور ہر شخص اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتا ہے.اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو قتل کرنے کے لئے جارہا ہو اور اس راز کا ایک تیسرے شخص کو بھی علم ہو مگر وہ پولیس میں اس وجہ سے اطلاع نہ دے کہ اگر میں نے اطلاع دی تو وہ پکڑا جائے گا اور اس کے بیوی بچوں کو تکلیف ہوگی تویہ ہرگز رحم نہیں کہلائے گا.اسی طرح اور ہزاروںمواقع انسانی زندگی میں ایسے آتے ہیں جب بہتر سے بہتراور اچھے سے اچھا کام بھی برا بن جاتا ہے اور انسان کا فرض ہے کہ اس سے بچے.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ عمل صالح کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور مومنوں کو ہدایت دی ہے کہ تم صرف ایسے کام نہ کر وجو بغیر نسبت کے تمہیں اچھے نظر آتے ہیں بلکہ تم وہ کام کیا کرو جو اردگرد کے حالات اور نسبت کے لحاظ سے بھی اچھے معلوم ہوتے ہوں.پس اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کے معنے یہ ہیں کہ سب لوگ گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لاتے اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں یعنی ایسے کام کرتے ہیں جو اضافی لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں.یورپ کے لوگ اس بات پر بڑا فخر کیا کرتے ہیں کہ نظریۂ اضافت آئن سٹائن نے ایجاد کیا ہے.حالانکہ یہ وہ نظریہ ہے جو آج سے تیرہ سو سال قبل قرآن کریم نے دنیا کے سامنے پیش کیا.اسی وجہ سے قرآن کریم میں ہر جگہ عملِ صالح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنے نظریۂ اضافت کے ہی ہیں یعنی کام اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اضافی لحاظ سے اچھے قرار پاتے ہیں.میں اوپر ایسے کاموں کی مثالیں پیش کرچکا ہوں جو بظاہر اچھے نظر آتے ہیں لیکن نسبتی لحاظ سے بعض دوسرے مقامات پر برے بن جاتے ہیں.اب میں ایک برے کام کی مثال پیش کرتا ہوں جو اضافی نقطۂ نظر
Page 249
سے قابل تعریف قرار پاتا ہے.فرض کرو کسی شخص کا باپ ایک جگہ بیٹھا ہے اور سانپ اس کے جسم پر چڑھ رہاہے مگر اسے کوئی علم نہیں کہ میرے جسم پر سانپ چڑھا جارہا ہے.یہ نظارہ اس کا لڑکا دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ذرا بھی غفلت کی تو سانپ میرے باپ کو ڈس لے گا.ایسی حالت میں اگر اس کے اند کچھ بھی عقل اور شعور کا مادہ پایا جاتا ہو تو وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرے گا کہ زور سے ایک ڈنڈا اس سانپ کو مارے یا اگر جوتا اس کے پاس پڑا ہو تو اسی کو اٹھا کو اس سختی کے ساتھ سانپ پر مارے کہ وہ مر جائے یا ڈر کر بھاگ جائے اور اسے کاٹنے کا موقع ہی نہ ملے.اب جہاں تک فعل کا سوال ہے یہی کہا جائے گاکہ اس نے اپنے باپ کوڈنڈا مارا یا جوتا اٹھا کر اس نے اپنے باپ کی طرف پھینکا.مگر جو شخص بھی اس واقعہ کو سنے گا یہ نہیں کہے گا کہ وہ بڑا نالائق اور خبیث تھا اس نے اپنے باپ کو جوتا مارا.بلکہ ہر شخص اس کی تعریف کرے گا اور کہے گا کہ وہ بڑا نیک اور سعادت مند بچہ تھا اس نے اپنے باپ کی حفاظت کی اور ایسی پھرتی سے کام لیا کہ سانپ کے لئے ڈسنے کا موقع ہی نہ آیا اور وہ مرگیا یا ڈر کر بھاگ گیا.پس جس طرح اچھے کام بعض دفعہ اضافی لحاظ سے برے بن جاتے ہیں اسی طرح برے کام بعض دفعہ اضافی لحاظ سے اچھے بن جاتے ہیں.اور یہ وہ نظریہ ہے جسے آئن سٹائن نے نہیں بلکہ سب سے پہلے قرآن کریم نے دنیا کے سامنے پیش کیا.قرآن کریم اس بات پر بار بار زور دیتا ہے کہ عمل وہی اچھا ہے جو صالح ہو اور جس میں تمام حالات کو مدّ ِنظر رکھ لیاگیا ہو.پس نظریہ اضافت عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ میں بتادیا گیاہے.لوگ کہتے ہیں کہ نیک عمل کرو.وہ کسی کا نام گڈ ایکشن رکھتے ہیں تو کسی کا نام بیڈ ایکشن.لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کردیتے ہیں کہ ایکشن اپنی ذات میں نہ کوئی اچھا ہے نہ برا.اگر کوئی ایکشن اچھا ہے تو نسبتی لحاظ سے اور اگر برا ہے تو نسبتی لحاظ سے.قتل کتنی بری چیز ہے لیکن لڑائی میں یہ کتنی اچھی چیز بن جاتا ہے.پس کوئی ایکشن اپنی ذات میںاچھا نہیں اور کوئی ایکشن اپنی ذات میں برا نہیں.صرف نسبت کے لحاظ سے ایک ایکشن اچھا بن جاتا ہے اور نسبت کے لحاظ سے ہی دوسرا ایکشن برا بن جاتا ہے.اور یہی معنے عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کے ہیں یعنی مومنوں کو وہ اعمال بجالانے چاہئیںجو اضافی طور پر اعلیٰ قرار دیئے جاسکیں (مگر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم اس اضافی نیکی کو بیان نہیں کرتا بلکہ انسان پر چھوڑ دیتا ہے تمام اضافی ضروری تفصیلات وہ خود بھی بیان کرتا ہے اور انتخاب کے اصول اس نے خود بیان کئے ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کروائے گئے ہیں).یہ امر پہلے بتایا جاچکا ہے کہ خُسْـرٌ کے معنے ضلالت کے بھی ہوتے ہیں، گھاٹے کے بھی ہوتے ہیں اور تباہی اور بربادی کے بھی ہوتے ہیں.اللہ تعالیٰ نے ان تینوں معانی پر روشنی ڈالنے کے لیے(۱) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
Page 250
۲)وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ(۳)وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میںتین قسم کے لوگوں کا ہی استثنیٰ کیا ہے.فرماتا ہے وہ لوگ جن میں یہ تین خاصیتیں پائی جائیں گی یعنی ان کے اندر ایمان بھی ہوگا ان کے اندر عمل صالح بھی ہوگا اور وہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ١ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پر بھی عمل کرنے والے ہوں گے وہ خُسْـر سے محفوظ رہیں گے.گویا خُسْـر کے بھی تین ہی معنے تھے اور اس کے بالمقابل استثنیٰ بھی تین قسم کے لوگوںکا ہی کیا گیا ہے اور اس طرح ایک ایک بات کا رد ایک ایک بات میں کر دیا گیا ہے.یعنی ایک قسم کا خُسْـر ایک بات سے،دوسری قسم کا خُسْـر دوسری بات سے،اور تیسری قسم کا خُسْـر تیسری بات سے رد کر دیا ہے.یہ بناوٹ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ قرآن کریم لغت کے معا نی کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے.کیونکہ خُسْـر کے بھی تین معنے تھے اور اس کے مقابل میں بھی تین باتیں ہی پیش کی گئی ہیں.خُسْـر کے پہلے معنے گمراہی اور ضلالت کے ہیںاس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کو رکھا.یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت صرف مومنوں کی جماعت گمراہی سے محفوظ ہوگی کیونکہ وہ وقت کے مامور پر ایمان لانے والی ہوگی اور سب لوگ گمراہ اور صداقت سے دور ہوں گے.پس گمراہی کے معنوں کو اٰمَنُوْا نے رد کر دیا.دوسرے معنے خُسْـر کے گھاٹے کے ہیں.اس کو رد کرنے اور لوگوںکو یہ بتانے کے لیے کہ گھاٹے سے بھی صرف مومنوں کی جماعت محفوظ ہوگی اللہ تعالیٰ نے عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کے الفاظ رکھ دئیے.گھاٹا آخر کیوں ہوتا ہے اسی لیے کہ انسان مناسب حال اعمال نہیں کرتا.اگر کوئی تاجر وقت پر کسی چیز کو خریدے گا نہیں.وقت پرکسی چیز کو بیچے گا نہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ اس کو اپنی تجارت میں خسارہ ہوگالیکن اگر وہ عمل صا لح اختیار کرے گا یعنی ایسے اعمال بجا لائے گا جو تجارت کے مناسب حال ہوںتو وہ گھا ٹے سے بچ جائے گا.پس مناسب حال اعمال انسان کو گھاٹے سے محفوظ رکھتے ہیں.چونکہ مومن مناسب حال اعمال بجا لائیں گے اس لئے وہ گھاٹے سے بھی محفوظ رہیں گے.خُسْـر کے تیسرے معنے ہلاکت اور بربادی کے ہیںاس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ١ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ رکھ دیا کہ مومن نہ صرف گمراہی سے محفوظ ہوں گے نہ صرف گھاٹے سے محفوظ ہوں گے بلکہ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ١ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی وجہ سے وہ ہلاکت اور بربادی سے بھی محفوظ ہوں گے.یہ صاف بات ہے کہ دنیا میں جب کوئی نئی صداقت آتی ہے لوگوں میں اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ اس کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں.اور جب کسی اقلیت کو اکثریت کی مخالفت کا سامناہو.حکومت اس کی مخالف ہو جائے، رعایا اس کی دشمن ہوجائے، تاجر اس کو مٹانے پر کمر بستہ ہو جائیں،صناع اس کی ہلاکت کے درپے ہو جائیں.اسی طرح عالم کیا اور جاہل کیا، بڑے کیا اور چھوٹے کیا سب کے سب اس ارادہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس کو کچل دیں گے تو
Page 251
ایسی حالت میںاس کے لیے تباہی سے بچنے کے دو۲ ہی ذرائع ہوتے ہیں.اوّل: اس کے پاس ہلاکت سے بچنے کے مکمل سامان ہوں.دوم: ان سامانوں سے کام لیا جائے.سامان نہ ہوںتب بھی انسان ہلاکت سے نہیں بچ سکتا اور اگر سامانوں سے کام نہ لیا جائے تب بھی انسان بربادی سے محفوظ نہیں رہ سکتا.پانی نہ ہو تب بھی انسان پیاسا مر جاتا ہے اور اگر پانی تو ہو مگر اس کو پیا نہ جائے تب بھی انسان مر جاتا ہے.پہلاذریعہ تو مومنوں کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مامور پر ایمان رکھتے ہیں.ان کی عملی قوت نہایت اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ایسے اعمال بجا لاتے ہیں جو موقع اور محل کے مناسب ہوں.اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک زائد بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی کامیابی کے متعلق خدا تعالیٰ کا وعدہ نظر آرہا ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا خواہ کس قدر مخالفت کرے وہ ہمیں کبھی مٹا نہیں سکتی.پس جہاں تک ہلاکت سے محفوظ رہنے کے سامانوں کا سوال ہے وہ مومنوں کو پورے طور پر حاصل ہوتے ہیں.ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے ان کے اندر قوت عمل بھی ہوتی ہے اور انہیں اپنی کامیابی کے متعلق خدا تعالیٰ کے وعدوں کی بناء پر کامل یقین بھی ہوتا ہے.لیکن اس کے بعد کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ سامانوںسے کام لیا جائے.وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ١ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خالی عمل صالح انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ جب وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ١ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا مقام کسی قوم کو حاصل ہوتا ہے تب وہ ہلاکت سے بچا کرتی ہے اس کے بغیر نہیں.وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کیا چیز ہے؟اس کے متعلق یہ ا مر یاد رکھناچاہیے کہ چونکہ حق کے ایک معنے صداقت کے بھی ہیں اس لیے وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے ایک معنے تو یہ ہوں گے کہ مومن اصول صداقت پر خود بھی قائم ہوں گے اور دوسروں کو بھی قائم کریں گے یعنی مومنوں کی یہ حالت ہو گی کہ ان میں سے ہر شخص نہ صرف خود صداقت کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا بلکہ دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرے گا کہ وہ ہمیشہ صداقت کو قبول کرنے کے لیے تیار رہا کریں.پہلی اور بڑی چیز جو کسی قوم کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے وہ غلط نظریوں پر اس قوم کا قائم ہو جانا ہے.جب کسی قوم کے سامنے غلط نظریے ہوں گے لازماً وہ غلط نتائج پر پہنچے گی اور غلط نتائج سے غلط اعمال ظاہر ہوں گے.پس وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ قوم غلط نظریوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی.ہاں جب کوئی سچی بات اس کے سامنے پیش ہو گی تو وہ اسے فوراً قبول کر لے گی.یہ امر انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جس چیز سے
Page 252
کسی کو وابستگی ہو جائے وہ اس سے ہٹا نہیں کرتا.صرف صداقت کی جستجو کا احساس ہی اسے ان بندھنوں سے نجات دیا کرتا ہے.ورنہ جب ایک لمبی عادت کسی غلطی کے متعلق قوم میں پائی جائے اور صداقت کی جستجو کا احساس اس کے قلب میں نہ رہے تو اس غلطی کو ترک کرنا لوگوں کے لیے سخت مشکل ہوتا ہے وہ سچائی پر اعتراض کرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے ہیںمگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں.جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو کئی لوگوں کے دلوں میں اس کے متعلق حسد پیدا ہو گیا مگرچونکہ وہ خود کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کولمبس نے اگر امریکہ دریافت کر لیا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے یہ کام تو ہم میں سے ہر شخص کر سکتا تھا.جو بھی جہاز میں سوار ہو کر نکل پڑتا آخر ایک دن اس نے امریکہ پہنچ ہی جانا تھا.یہ کوئی ایسا کارنامہ نہیں جسے سراہا جائے اور جس کے سر انجام دینے پر کولمبس کی تعریف کی جائے.جب کولمبس کو معلوم ہوا کہ میرے متعلق بعض لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں.تو اس نے ایک پارٹی میں بہت سے لوگوں کو مدعو کیا اور اپنی جیب میں سے ایک انڈا نکال کر ان سے کہا کہ اسے میز پر کھڑا کر دو.سب ادھر ادھر دیکھنے لگے اور کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ انڈے کو میز پر کس طرح کھڑا کیا جائے.کولمبس نے سوئی نکالی ا ور انڈے میں سوراخ کرکے اس میں سے تھوڑا سا لعاب نکالا اور انڈے کو چپکا کر میز پر کھڑا کردیا.اس پر لوگ کہنے لگے یہ کون سی بڑی بات تھی یہ تو ہم بھی کرسکتے تھے.کولمبس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم امریکہ کے متعلق یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کولمبس نے اس کی دریافت کرلی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں.اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی دریافت کرلیتے.امریکہ دریافت کرنے کا تو تمہیں موقع نہیں ملا لیکن انڈے کو میز پر کھڑا کرنے کا تو تمہیں موقع مل گیا تھا پھر تم کیوں اس کو کھڑا نہ کرسکے.اصل بات یہ ہے کہ صداقت کے اصول بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں.سوال صرف کام کرنے اور صداقت سے وابستگی پیدا کرنے کا ہوتا ہے.جن لوگوں کے دلوں میں سچائی کی تلاش کا جذبہ ہوتا ہے وہ معمولی معمولی باتوں سے بڑے بڑے اہم نتائج اخذ کرلیتے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ سچائی ہمیں کہاں سے ملی ہے.وہ سچائی کی طرف ایک پیاسے کی طرح اُمڈ کر جاتے ہیںاور اپنے سابق غلط خیالات کو فوراً ترک کردیتے ہیں لیکن جن لوگوں کے دلوں میں صداقت کا کوئی احساس نہیں ہوتا ان کے لئے اپنی پرانی غلطیوں کو چھوڑنا سخت مشکل ہوجاتا ہے.آخر یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں بلکہ آسمان پر زندہ موجود ہیں.جب ساری دنیا آدم سے لے کر اب تک مرتی چلی آئی ہے تو یہ کس طرح ہوسکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت سے بچ جاتے اور
Page 253
وہ تمام بنی نوع انسان کے خلاف زندہ آسمان پر چلے جاتے مگر چونکہ مسلمان اس عقیدہ کے ساتھ وابستہ ہوگئے ہیں اس لئے انہیں اس کو چھوڑنا ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے.اسی طرح اور کئی قسم کے غلط مسائل ہیں جو زمانہ نبوت سے بُعد کی وجہ سے مسلمانوں میں رائج ہوچکے ہیں اور جن سے ادھر ادھر ہونا ان پر نہایت شاق گذرتا ہے.لیکن اگر کوئی شخص ہمت سے کام لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لے آئے تو یہ طوق اور سلاسل ایک آن میں کٹ جاتے ہیں اور اسے کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی.اور لوگوں کو تو یہ نظرآتا ہے کہ فلاں بات امام غزالیؒ نے کہی ہے ہم اسے کس طرح چھوڑ دیں.فلاں بات جنیدؒ نے کہی ہے ہم اسے کس طرح چھوڑ دیں.فلاں بات سیدعبدالقادر جیلانیؒ نے کہی ہے ہم اسے کس طرح چھوڑ دیں.فلاں بات امام رازیؒ نے کہی ہے ہم اسے کس طرح چھوڑ دیں.فلاں مسئلہ امام ابوحنیفہؒ نے بیان کیا ہے ہم اسے کس طرح چھوڑ دیں.فلاں مسئلہ امام شافعیؒ نے بیان کیا ہے ہم اسے کس طرح چھوڑ دیں.لیکن ایک احمدی کے لئے ان میں سے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک مامور پر ایمان لاچکا ہوں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سامنے ہے جو کچھ وہ کہے گا وہ درست ہوگا اور جس بات کی وہ تردید کرے گا وہ غلط ہوگی.مجھے اس بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں کہ امام رازی یا امام غزالی یا امام ابوحنیفہ نے کیا کہا ہے میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اور مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے کیا ہدایت پائی ہے.غرض ہر قوم میں مختلف قسم کی غلطیاں پائی جاتی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے توپچھلے سارے تعلقات کٹ جاتے ہیں.آخر بڑے بڑے آدمی بھی تو غلطی کرسکتے ہیں.اگر ہزار مسائل وہ نہایت اعلیٰ درجہ کے پیدا کرتے ہیں تو ایک دو مسئلوں میں ان سے غلطیاں بھی ہوجاتی ہیں.مگر ایک ایک غلطی اکٹھی ہوتے ہوتے غلطیوں کا ایک طومار بن جاتا ہے جس میں لوگ پھنس جاتے ہیں اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم اس دلدل میں سے کس طرح نکلیں اگر ہم نکلے تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ ہم اپنے بزرگوںکے خلاف قدم اٹھارہے ہیں.پس جب تک کوئی شخص نبی پر ایمان نہیں لاتا وہ کئی قسم کی مشکلات میں پھنسارہتا ہے.لیکن ادھر اسے نبوت پر ایمان نصیب ہوتا ہے اور ادھر یک دم اس کے تمام بوجھ اتر جاتے ہیں اور وہ رسیاں جنہوں نے اس کو جکڑا ہوتا ہے سب ایک ایک کرکے ٹوٹ جاتی ہیں.اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو ایمان نصیب ہوتا ہے اس کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں( مسلم کتاب الایمان باب کون الاسلام یھدم ما قبلہ ).اس کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی نبی پرایمان لاتا ہے اس کی پچھلی تمام روایتی قیود ختم ہوجاتی ہیں.
Page 254
وہ تمام رسیاں جن سے اس کا جوڑ جوڑ جکڑا ہوا ہوتا ہے کٹ جاتی ہیں اور وہ حریت اور آزادی کی فضا میں پہلی مرتبہ سانس لیتا ہے کیونکہ نبی کے ماننے والے اس اصل پر قائم ہوتے ہیں کہ جو سچی بات ہے اس کو ہم نے ماننا ہے اور جو غلط بات ہے اس کو ہم نے نہیں ماننا خواہ اسے کسی کی طرف سے پیش کیا جارہا ہو.گویا وہ طوق جنہوں نے اس کی گردن کو جھکایا ہوا ہوتا ہے اور وہ سلاسل جو اس کے پائوں میں پڑی ہوتی ہیں سب کٹ جاتی ہیں اور وہ سچائی کا علمبردار بن جاتا ہے.تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے چھ معنے پس تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے پہلے معنے یہ ہیں کہ مومن اصول صداقت پر خود بھی پوری طرح قائم ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.(۲) حَقّ کے ایک معنے جیسا کہ اوپر بتایا جاچکا ہے اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں.اس لحاظ سے تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے یہ معنے ہیں کہ مومن خدا تعالیٰ سے خود بھی مخلصانہ تعلقات رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے مخلصانہ تعلقات پیدا کرنے کی نصیحت کرتے ہیں.درحقیقت اقوام میں دیرینہ عادات کی وجہ سے آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کا وجود بالکل غائب ہوجاتا ہے اور اس کی بجائے ایک نئی شکل پیداہوجاتی ہے جس کی وہ پرستش کرنے لگتے ہیں.آج دنیا میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں سب کی یہی حالت ہے.عیسائیت کو دیکھ لو، ہند ومذہب کو دیکھ لو.اور مذاہب پر نظر ڈال لو.سب کی اصلی شکل تو مٹ چکی ہے لیکن قولی روایات نے ان کو ایک نئی شکل دے دی ہے جس کے وہ پرستار بنے ہوئے ہیں.یہ نئی شکل مذہب کی قائم کردہ نہیں ہوتی بلکہ قوم کے بگڑے ہوئے خیالات و تصورات کی قائم کردہ ہوتی ہے.جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی آتا ہے تو یہ سارے بت ایک ایک کرکے گر جاتے ہیں اور اصلی خدا لوگوں کے سامنے آجاتا ہے تب لوگ بت پرستی کے گڑھوں میں سے نکلتے اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی محبت کے میدان میں بڑھنے لگتے ہیں.پس تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے ایک معنے یہ ہیں کہ مومن اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ تعلقات رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم حقیقی خدا کی پرستش کرو اور اس سے اپنے تعلقات بڑھائو.بتوں کی پرستش میں تم اپنا وقت ضائع مت کرو.(۳) حَقّ کے تیسرے معنے عدل کے ہیں.اس لحاظ سے تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے معنے یہ ہیں کہ مومن خود بھی عدل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عدل سے کام لینے کی نصیحت کرتے ہیں.درحقیقت ایک بڑی بھاری خرابی قومی روایات کی وجہ سے یہ پیدا ہوجاتی ہے کہ لوگ عدل و انصاف سے کام لینا ترک کردیتے ہیں.ہزاروں خاندان دنیا میںایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی پرانی روایات پر جمے ہوئے ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم میں سے فلاں نے یہ یہ
Page 255
خرابی کی مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم خاندان کے افراد کو چھوڑ نہیں سکتے ہم مجبور ہیں کہ ان کا ساتھ دیں اور اپنے خاندان کو دوسروں کے مقابلہ میں ذلیل نہ ہونے دیں.پس قدیم تعلقات کی وجہ سے عدل کی روح بالکل مٹ جاتی ہے لیکن جب نبی آتا ہے تو دنیامیں ایک انقلاب پیدا ہوجاتا ہے اور عدل و انصاف کی وہ روح جو پائوں تلے مسلی جارہی ہوتی ہے ازسرنو زندہ ہوجاتی ہے وہ لوگ جنہیں اس پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے کہتے ہیںکہ ہم دنیا میں انصاف قائم کریں گے.ہم مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے.ہم ظالم کو اس کے کیفرکردار تک پہنچائیں گے.ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ سرمایہ دارمزدور پر ظلم کرے یا امیر غریب کو لوٹنے کی کوشش کرے وہ عدل و انصاف کے پیکر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے.(۴) حَقّ کے چوتھے معنے اَلْیَقِیْنُ بَعْدَ الشَّکِّ کے ہیں.اس لحاظ سے تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے یہ معنے ہوں گے کہ مومن شکوک و شبہات پر یا قیاس و تخمین پر اپنے ایمان کی بنیاد نہیں رکھتے بلکہ اپنے عقائد کی بنیاد یقین پر رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے متعلق محض رسمی اعتقاد پیدانہ کرو بلکہ وہ ایمان پیدا کرو جو مشاہدہ پر مبنی ہوتا ہے.درحقیقت یقین پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کا وجود ہی ہوتا ہے.جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے اور وہ اپنی صداقت کے زندہ نشانات لوگوں کے سامنے پیش کرتاہے تو شکوک و شبہات بالکل مٹ جاتے ہیں اور قیاس و تخمین کی بجائے ایمان کی بنیاد مشاہدہ پر آجاتی ہے پس تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے معنے یہ ہیں کہ مومن خود بھی یقین پر قائم ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ تم خدا تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین پیدا کرو.رسمی ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاسکتا.آج مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے کہ ان کے اندر اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محض رسمی ایمان پایا جاتا ہے.وہ ایمان جس کی یقین پر بنیادیں ہوتی ہیں اور وہ ایمان جو مستحکم اور غیرمتزلزل ہوتا ہے اس کا وجود ان میں کلی طور پر مفقود ہے.بے شک وہ بظاہر اسلام کو سچا مذہب سمجھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم اسلام کیوںمانتے ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیوں ایمان رکھتے ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض اس لئے سچا مانتے ہیںکہ ان کے ماں باپ یہ عقیدہ رکھتے تھے یا اس لئے سچا مانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیداہو گئے ہیں.اس سے بڑھ کر ان کے پاس اپنے مذہب کی سچائی کاکوئی ثبوت نہیں ہوتا.میں نے خود کئی تعلیم یافتہ لوگوں سے یہ سوال کرکے دیکھا ہے مگر مجھے ہمیشہ ان کی طرف سے
Page 256
مایوس کن جواب ملا ہے جو ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں اپنے مذہب کی سچائی پر کوئی یقین نہیں وہ محض رسمی رنگ میں اسلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں ورنہ ان کے دل کے اندرونی گوشے یقین اور وثوق سے بالکل خالی ہیں.ایک بہت بڑے آدمی جو اس وقت ہندوستان میں چوٹی کے علمی مقام پر ہیں ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوکیوں مانتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانتا ہوں.حقیقت بھی یہی ہے کہ اب مسلمانوں میں محض رسمی ایمان رہ گیا ہے اور وہ مذہب پر غور کرنے کے عادی نہیں رہے.اسی وجہ سے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں ماموریت کا اعلان فرمایا تو مسلمان آپ پر اعتراض کرنے لگ گئے ہیں کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خیالی وجود کو مان رہے تھے.حقیقت ان کی نظروں سے پوشیدہ تھی.پس تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے معنے یہ ہیں کہ نبی کوماننے والے خود بھی یقین پر قائم ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی رسمی ایمان کے دائرہ سے نکال کر حقیقی ایمان کے دائرہ میں لانے کی کوشش کرتے ہیںاور چونکہ ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر مانیں اندھی تقلید اختیار نہ کریں اس لئے وہ ہربات کی حکمت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.نماز پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو سمجھ کر رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو سمجھ کر کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں تو سمجھ کر دیتے ہیں، صدقہ و خیرات میں حصہ لیتے ہیں تو سمجھ کر لیتے ہیں.اسی وجہ سے ان کے کاموں میں بشاشت پائی جاتی ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ ان کے کاموں کی بنیاد یقین پر ہوتی ہے تخمینہ اور قیاس پر نہیں ہوتی.(۵) حَقّ کے ایک معنے حزم اور احتیاط کے بھی ہیں.اس لحاظ سے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے یہ معنے ہیں کہ مومن حزم پر قائم ہوتے اور دوسروں کو بھی اس پر قائم کرتے ہیں.یہ خوبی بھی نبی پر ایمان لانے کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے باقی تمام اقوام تہوّر کا شکا ر Desperate ہوکر اپنی طاقت کو بالکل کھو بیٹھتی ہیں لیکن نبی پر ایمان لانے والوں کے سامنے ایک بلند مقصد ہوتا ہے.دین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ان میں سے ایک ایک فرد پر عائد ہوتی ہے اور چونکہ وہ ایک بہت بڑی امانت کے حامل ہوتے ہیں.اس لئے وہ اونچ نیچ کو دیکھتے ہوئے سنبھل سنبھل کر اپنے قدم بڑھاتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ وہ گر پڑیں اور جس جھنڈے کو انہوں نے فتح و کامرانی کے ساتھ دشمن کے مقام پر گاڑنا ہے وہ سرنگوں ہوجائے.لیکن دوسری قومیں صرف اتنا جانتی ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مر جائیں یا ماردیں.اس وجہ سے وہ اندھا دھند حملہ کرتی اور اپنی طاقت کو ضائع کردیتی ہیں.پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے ہر کام میں حزم و احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہمیشہ محتاط راہ پر چلنے کی تاکید کرتے ہیں.
Page 257
(۶)اسی طرح حَقّ کے ایک معنے موت کے بھی ہیں.اس لحاظ سے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے یہ معنے ہیں کہ مومن خود بھی موت کو خوشی سے قبول کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں اپنی جان اللہ تعالیٰ کے راستہ میں قربان کر دو.گویا مومن جماعت قربانی اور ایثار کی مجسمہ ہوتی ہے اور موت کا ڈر اس کے دل کے کسی گوشہ میں بھی نہیں ہوتا.وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیشگوئیاں ہماری کامیابی کے متعلق موجود ہیں اگر ہم زندہ رہے تو فاتح ہوں گے اور اگر مرگئے تو اگلے جہاں میں آرام سے زندگی بسر کریں گے.دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے.زندگی میں بھی فائدہ ہے اور موت میں بھی فائدہ ہے.زندہ رہے تو کامیابی یقینی ہے اور اگر مرگئے تواگلے جہاں میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے وارث ہوں گے.اس یقین کی وجہ سے جو دلیری مومنوں میں پائی جاتی ہے اس کاعشر عشیر بھی کسی اور قوم میں نہیں ہوتا.جب بدر کے میدان میں کفار اور مسلمان ایک دوسرے کے مقابل میں پہنچ گئے تو کفار نے ایک شخص کو یہ پتہ لگانے کے لئے بھیجاکہ مسلمان کتنے ہیں اور ان کے سازوسامان کاکیا حال ہے.معلوم ہوتا ہے وہ آدمی نہایت ہوشیار تھا کیونکہ واپس جاکر اس نے کہا میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلمان تین سو سوا تین سو کے قریب ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی کیونکہ مسلمان تین سو تیرہ تھے.مگر اس نے کہا اے میرے بھائیو! میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لڑائی کا خیال بالکل چھوڑ دو کیونکہ میں نے اونٹوں اور گھوڑوں پر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو سوار دیکھا ہے (السیرۃ ابن ھشام ذکر رؤیا عاتکۃ بنت عبد المطلب ).یعنی ان میں سے ہر شخص کے چہرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج اس نیت اور ارادہ کے ساتھ آیا ہے کہ میں زندہ واپس نہیں جائوں گا.اور جو قوم اس نیت اور ارادہ کے ساتھ میدان میں آئے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوتا.یہی تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے معنے ہیں کہ مومن نڈر اور بہادر ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے بلکہ خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ تم موت سے مت ڈرو گویا تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں مومنوں کے ایمان اور یقین کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ انہیں صداقت پر اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ موت کو برا سمجھیں اسے اپنے لئے خوشخبری سمجھتے ہیں اور نہ صرف خود موت کے لئے تیار رہتے ہیں بلکہ اپنے ساتھیوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو موت کے لئے تیار رہا کرو.پھر فرماتا ہے وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ مومنوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی صبر کرتے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں.صبر کے معنے یہ ہیں کہ ان کے اندر مظالم کو برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے.اسی طرح صبر کے ایک معنے استقلال کے بھی ہیں گویا مومنوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی سچائی کو قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں اس بات کی کچھ پروا نہیںہوتی کہ دشمن انہیں مصائب میں مبتلا کرتا ہے یا ان پر
Page 258
عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بڑی ہمت کے ساتھ تمام مشکلات کوبرداشت کرتے ہیں اسی طرح نیکیوں پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں.یعنی استقلال کا مادہ ان میں پایا جاتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیںکہ تمہیں اپنے اندر استقلال اور مصائب کو برداشت کرنے کا مادہ پید اکرناچاہیے.ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مومن کا مذہب قومی مذہب ہوتا ہے اس کی نیک خواہشات صرف اپنی ذات تک محدود نہیںہوتیں بلکہ تمام بنی نوع انسان تک وسیع ہوتی ہیں.وہ ایک عالمگیر مواخات کا زبردست حامی ہوتا ہے اور تمام چھوٹوں اور بڑوں کو ایک سلسلہ میں منسلک کرنا چاہتا ہے.وہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف میں نیک بنوں بلکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرا ساتھی بھی نیک ہو اور دنیا میں صلح اور آشتی کی بنیاد ایسی مضبوط ہو کہ کوئی زلزلہ اس کو جنبش میں نہ لاسکے.یہی باتیں ہیں جو دنیا میں قوموں کو ہلاکت سے بچایا کرتی ہیں.جس قوم کے افراد میں یہ باتیں پائی جائیں اس قوم کو کوئی ہلاک نہیں کرسکتاخواہ اس کے دس افرا دہوں، سو ہوں، ہزار ہوں، دس ہزار ہوں وہ بہرحال غالب آتی اور دنیا میں قائم رہتی ہے.پس فرماتا ہے وَ الْعَصْرِ.اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ.اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ١ۙ۬ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.ہم زمانہ نبوت کو یا دَہر کو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ کو اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ چونکہ یہ تین صفتیں مومنوں کے اندر پائی جائیں گی اس لئے وہ یقیناً جیت جائیں گے اور چونکہ یہ تین صفتیں ان کے دشمنوں کے اندر نہیں پائی جائیں گی اس لئے وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ضرور ہاریں گے.
Page 259
سُوْرَۃُ الْھُمَزَۃِ مَکِّیَّۃٌ سورئہ ہمزہ یہ مکی سورۃ ہے وَھِیَ تِسْعُ اٰیَاتٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اس کی بسم ا للہ کے سوا نو آیات ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ ہمزہ مکی ہے سورۂ ہمزہ اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہے.مستشرقین یورپ بھی اسے ابتدائی مکی سورتوں میں سے قرار دیتے ہیں.اس سورۃ میں زمانۂ رسالت کے لوگوں کا حال بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دکھ دیتے تھے اور اپنے اموال پر مغرور تھے.ھُمَزوَ لُمَز کے معنی عیب چینی اور غیبت کے بھی ہوتے ہیںاور دکھ اور تکلیف دینے کے بھی ہوتے ہیں اور یہ دونوں معنی یہاں چسپاں ہوتے ہیں.یعنی وہ دکھ بھی دیتے تھے اور عیب چینی اور غیبت بھی کرتے تھے.پھر اس سورۃمیں یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود اہل مکہ کے مالدار ہونے کے اور باوجوداپنے اموال پر فخر کرنے کے اور باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے ان کی طرف کئی قسم کے عیوب منسوب کرتے تھے اور ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے پھر بھی وہ لوگ ایک ایسے دکھ میں مبتلا ہو جائیں گے اور ایک ایسے عذاب سے پکڑے جائیں گے کہ ان کے دلوں کا چین بالکل اڑ جائے گا اور وہ آخر ہلاک اوربرباد ہو جائیں گے.ترتیب سورۃ ہمزہ کا تعلق سورۃ عصر سے اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے تعلق اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے.یعنی یہ سورتیںیکے بعد دیگر ے باری باری اسلام کے ابتدائی دور اور آخری دور کے متعلق آرہی ہیں پہلی سورۃ یعنی وَ الْعَصْرِ کا تعلق زیادہ تر آخری دور کے ساتھ ہے.اب اس سورۃ میںاسلام کے پہلے دور کا ذکر کیا گیا ہے.در حقیقت یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں جو قرآن کریم کے آخر میں ترتیب مستقل کے طور رکھی گئی ہیں ترتیب نزول کے مطابق ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی تھیں سوائے چند ایک کے جو بعد از ہجرت نازل ہوئیں.ان سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دونوں دوروں کامتوازی ذکر کیا گیا ہے مگر جیساکہ قرآن کریم کا اسلوب ہے یہ ذکر اس طرح ہے کہ اس زمانہ کے لوگ آخری دور والی سورتوں سے بھی فائدہ اٹھاسکتے تھے اور دور اوّل والی سو ر توں سے آج کل کے لوگ بھی برابر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں.یہ قرآن کریم کا
Page 260
عظیم الشان معجزہ ہے کہ جس وقت اسلام صرف چند افراد پر مشتمل تھا اسی وقت اس کی ترقی کے بعد تنزّل اور اس کے تنزّل کے بعد کی ترقیات کا ذکر کیا جا رہا تھا اس قدر عظیم الشان علم غیب اور کسی کتاب میں نہیں پایا جاسکتا.گویا اللہ تعالیٰ کے اظہار علی الغیب کا کمال قرآن کریم میںاپنی مکمل شکل میںظاہر ہوا ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے(شروع کرتا ہوں) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۙ۰۰۲ ہر غیبت کرنے والے (اور) عیب چینی کرنے والے کے لئے عذاب (ہی عذاب) ہے.حلّ لُغات.وَیْلٌ.وَیْلٌ عذاب کے نازل ہونے یاہلاکت کے نازل ہونے کے معنوں میں آتا ہے (اقرب) یعنی اس بات کے بتانے کے لئے کہ جس شخص کے متعلق یہ لفظ بولا جاتا ہے اس کو اپنے مال یا عزت یا راحت و چین کے بارہ میں کوئی تکلیف پہنچے گی.گویا وہ تمام چیزیں جن کو انسان اچھا سمجھتا ہے یا جن کو اپنی عزت اور آرام کا موجب سمجھتا ہے اور جن کے ضائع ہونے پر وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے ان کے کھوئے جانے کی طرف جب اشارہ کرنا مقصود ہو تو وَیْلٌ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پس وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ کے معنے یہ ہوئے کہ عذاب آنے والا ہے ہر هُـمزة اور لُمزۃ پر یا اپنی عزت کی چیزیںاور راحت وآرام کی چیزیں هُـمزة اور لُمزة کھونے والا ہے.یہ لفظ جب کسی کے لئے استعمال کیا جائے تو اس کے یہ معنے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس عذاب اور ہلاکت کا مستحق ہی ہے یوں ہی اتفاقی یا ظلماً اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوا مثلاً اگر کسی شخص پر ظلماً کوئی ایذاء وارد ہو تو اس کے بارہ میں یہ نہ کہیںگے کہ وَیْلٌ.هَـمَزَ اور لَمَزَ عربی زبان کے لحاظ سے ایک ہی معنے رکھتے ہیں کیونکہ م اور ز ان دونوں میں پائے جاتے ہیں.اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ حروف بھی معنوں پر دلالت کرتے ہیںاور جب ایک قسم کے حروف ہوں تو ان کے معنوں میں اشتراک پایا جاتاہے.ان دونوں لفظوں میں م ز مشترک ہیںصرف فرق یہ ہے کہ ایک سے پہلے ہ ہے اور ایک سے پہلے ل آخری دونوں حروف دونوں لفظوں میں مشترک ہیںجس کے یہ معنے ہیں کہ ان کے معنوں میں شدید اتصال ہونا چاہیےچنانچہ ایسا ہی ہے اور دونوں کے معنے بہت حد تک مشترک ہیں.چنا نچہ لغت میں لکھا ہے
Page 261
ھَمَزَہٗ ھَمْزًا: غَـمَزَہٗ.۱یعنی اس کو اشارہ کیا.نَـخَسَہٗ.۲ اس کو انگلی ماری.دَفَعَہٗ.۳ اس کو دھکا دیا.ضَـرَبَہٗ.۴ اس کو مارا.عَضَّہٗ.۵ اس کو کاٹا.اِغْتَابَہٗ.۶ اس کی غیبت کی.کَسَـرَہٗ.۷ اس کو توڑ دیا.ھَمَزَ.۸ الشَّیْطَانُ الْاِنْسَانَ : ھَمَسَ فِیْ قَلْبِہٖ وَسْوَاسًا.شیطان نے انسان کے دل میںوسوسہ ڈالا.ھَمَزَ.۹ بِہِ الْاَرْضَ: صَـرَعَہٗ اس کو زمین پر دے مارا.ھَمَزَ.۰ الْفَرَسَ: نَـخَسَہٗ بِالْمِہْمَازِ لِیَعْدُوَ.گھوڑے کو ایڑ لگائی تا کہ وہ تیزی سے دوڑے.ھَمَزَ.۱۱ الْعِنَبَ : عَصَـرَہٗ.انگوروں کو نچوڑا (اقرب) الغرض ھمز کے معنے آنکھ مارنے کے بھی ہیں.انگلی مارنے کے بھی ہیں.دھکا دینے کے بھی ہیں.کاٹنے کے بھی ہیں.پیٹنے کے بھی ہیں.اسی طرح ھمز کے معنے غیبت کے بھی ہیں.توڑنے کے بھی ہیں دل میں وسوسہ پیدا کرنے کے بھی ہیں.زمین پر اٹھا کر دے مارنے کے بھی ہیں.گھوڑے کو ایڑ مارنے کے بھی ہیںاور کسی چیز کو نچوڑنے کے بھی ہیں.لَمَزَ.لَمَزَ(یَلْمِزُ لَمْزًا) کے معنے ہیں عَابَہٗ اس پر عیب لگا یا اور اس کے معنے اَشَارَ اِلَیْہِ بِعَیْنِہٖ وَنَـحْوِھَا مَعَ کَلَامٍ خَفِیٍّ کے بھی ہیں (اقرب) یعنی جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوںاور کوئی ایسا شخص آجائے جسے ذلیل سمجھا جاتا ہو تو وہ لوگ جو آپس میںگہرے دوست ہوتے ہیںاس کی طرف آنکھ سے اشارہ کرتے ہیںجس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لو جی فلاں شخص بھی ہماری مجلس کو خراب کرنے کے لئے آگیاہے.مگر لَمز اس وقت آنکھ سے اشارہ کرنے کو کہتے ہیںجب اشارہ کے ساتھ کوئی بات بھی آہستگی سے کہی جائے مثلاً آنکھ سے اشارہ کیا اور سا تھ ہی کہہ دیا کہ’’تشریف لے آئے ہیں‘‘ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری مجلس کو خراب کرنے کے لئے آ گیا ہے.گو الفاظ یہ استعمال کئے جاتے ہیںکہ’’تشریف لے آئے ہیں‘‘.پس لَمز کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیںجب اشارہ کے ساتھ بعض الفاظ بھی کہے جائیں.اسی طرح اس کے معنے دھکا دینے کے بھی ہیں.مارنے کے بھی ہیں اور عیب چینی کے بھی ہیںخصوصاً اس عیب چینی کے جو کسی کے سامنے کی جائے.ان معنوں سے پتہ لگتا ہے کہ هُـمَزَة اور لُمَزَة کے معنوں میں شدید اشتراک پایا جاتا ہے دونوں کے معنے مارنے کے بھی ہیں.دونوںکے معنے دھکا دینے کے بھی ہیںاور دونوں کے معنے عیب چینی کے بھی ہیں.لیکن ھمز میںاس عیب چینی کی طر ف اشارہ ہوتا ہے جو غیبت کا رنگ رکھتی ہو یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے کی جائےاور لمز میں اس عیب چینی کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو سامنے کی جائے.پھر ھمز میں توڑنے کے معنے بھی شامل ہیں.اس لحاظ سے وہ حرکت جو ہاتھ یا سر سے اس طرح کی جائے جس طرح کوئی چیز ٹوٹ کر نیچے گرتی ہے مثلاً ہاتھ کو جھٹکا دے دیا جائے یا
Page 262
گردن کو خاص طریق پر حرکت دی جائے تو اس کے لئے بھی ھمز کا لفظ استعمال ہوتا ہے.جہاںتک مارنے اور دھکا دینے کا سوال ہے یہ معنے هـمز اور لمز دونوں میں پائے جاتے ہیں.اسی طرح عیب چینی کے معنے بھی دونوں میں پائے جاتے ہیںلیکن ھمز میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے عیب چینی کی جائے اور لمز میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ منہ پر عیب چینی کی جائے پھر ھمز کے ایک زائد معنے نچوڑنے کے بھی ہیں.تفسیر.صحابہ اور تابعین میں آیت وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ کے معنے میں اختلاف مفسرین میں حتی کہ صحابہؓ اور تا بعین میں بھی اس آیت کے متعلق کثیر اختلاف پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوںالفاظ لغت میںقریباً ہم معنی ہیں.کسی نے ھمز کے معنے عیب چینی کے کئے ہیں اور لمز کے معنے غیبت کے کئے ہیںاور کسی نے لمز کے معنے عیب چینی کے کئے ہیںاور ھمز کے معنے غیبت کے کئے ہیں.لیکن اس اختلاف کی اصل وجہ وہی ہے جو میں نے اوپر بیان کی ہے کہ یہ دونوں لفظ قریب المعنیٰ ہیںاور اس وجہ سے مختلف لوگوں کو ان کے معنے کرنے میںشبہ واقع ہو گیا ہے چونکہ یہ دونوں الفاظ قریب المعنیٰ تھے وہ پورے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس آیت میں ھمز کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اور لمز کن معنوں میں استعمال ہوا ہے.اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لغت کی تدوین بعد کے زمانہ میں ہوئی ہے.جب کسی علمی زبان کا دنیا میں رواج شروع ہوتا ہے اسی وقت اس کی لغت مکمل نہیں ہو جاتی بلکہ آہستہ آہستہ لغت کی کتابیں مدوّن ہونی شروع ہوتی ہیں تب لوگ کسی صحیح نتیجہ پر پہنچتے ہیںاس سے پہلے نہیں.اسی وجہ سے جہاں تک لغت کا سوال ہے ابتدائی زمانہ کے مفسرین کے معنے ایسی تعیین نہیں کرتے جیسی تعیین بعد کے مفسرین کرتے ہیںکیونکہ بعد میں آنے والے مفسرین کو لغت کی مکمل کتا بیں مل گئیں جو پہلے موجود نہیں تھیں.مثلا ہمارے زمانہ میں تاج ا لعروس موجود ہے، لسان العرب موجود ہے اور لغت کی یہ دونوں کتا بیں اپنے اندر بہت وسیع معلومات رکھتی ہیں اور ان میں بڑی بڑی باریکیاں بیان ہیں.لیکن تاج العروس آج سے تین سو سال پہلے لکھی گئی تھی اور لسان العرب آج سے چھ سات سو سال پہلے لکھی گئی تھی.اس سے قبل ایک لمبا عرصہ ایسا گذرا ہے جس میں لغت کی کتابیں مدوّن نہیں تھیں.گو عربی زبان کا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ تھوڑے عرصہ میں ہی اس نے اپنی لغت کو عروج تک پہنچا دیا.مگر پھر بھی میرے نزدیک ابھی اس میں ترقی کی گنجائش ہے اور یہ لغت زیادہ بہتر طور پر مکمل ہو سکتی ہے کیونکہ آئمہ لغت نے بعض جگہ سیر کن بحثیں نہیں کیں.لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس قدر عظیم الشان علمی ذخیرہ ہے کہ انگریز مصنف لین پول ایک جگہ عربی لغت کا ذکر
Page 263
کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کاش ہماری زبان کی کوئی ایسی لغت ہوتی جیسی عربی زبان کی ہے.گو اس فقرہ کے ذریعہ اس نے تسلیم کیا ہے کہ عربی زبان کی لغت مکمل ہے مگر میرا خیال ہے جس رنگ میں ہم لغت کی تحقیق و تد قیق کرتے ہیں اور جس قسم کی تحقیق کی قرآن کریم کی تفسیر کے لئے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے اس کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے ابھی اور زیادہ لغت کی تحقیق کی ضرورت ہے.پرانی لغتوں میںایک خفیف سا نقص یہ پایا جاتا ہے کہ بعض جگہ مفسرین کے اقوال کو بھی لغت میں شامل کر لیا گیا ہے.اگر اس نقص کو دور کر دیا جائے اور لغت کی حکمت کو زیادہ واضح کیا جائے تو عربی زبان کی ایک ایسی لغت مکمل ہو جائے گی جس کی مثال دنیا کی اور کسی زبان میں نہیں مل سکے گی.بہر حال جب دو قریب المعنیٰ الفاظ آجائیںتو ان دونوں کا آپس میںجو اختلاف ہوتا ہے صرف اس کو لیا جاتا ہے.کیونکہ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب دو لفظ بولے جائیں اور وہ دونوں آپس میں مشترک معنے رکھتے ہوں تو دوسرے لفظ کے صرف وہ معنے لینے چاہئیں جن میں اس کا پہلے سے اختلاف پایا جاتاہو.یہ امر ظاہر ہے کہ مشترک معنوں کے لئے دو لفظوں کی ضرورت نہیں ہو سکتی ایک لفظ بھی پورا کام دے سکتا ہے.پس جب دو لفظ اکٹھے استعمال ہوں اور دونوں قریب المعنیٰ ہوں تو ہمیشہ دوسرے لفظ کے وہ معنے لئے جاتے ہیں جن میں وہ پہلے سے مختلف ہوں.ھمز اور لمز کے معنے کی تعیین اس اصول کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے دو صورتیں ہو سکتی ہیں.پہلی صورت تو یہ ہے کہ ھمز کو مار پیٹ کے معنوں میں لیا جائے کیونکہ ھمز میں ماریا جسمانی ضرب کے معنے زیادہ پائے جاتے ہیں.اصل میں ھمز کے معنے کسر یعنی توڑنے کے ہوتے ہیں پس چونکہ اس کے اصل معنے توڑنے کے ہیں اس لئے ھمز میں مارنے پیٹنے کے معنے زیادہ پائے جاتے ہیں.پس ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ھمز کے معنے مارنے پیٹنے کے لیں اور لمز کے دوسرے معنے لے لیں یعنی عیب چینی وغیرہ کے.اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ھمز کے معنے ہم غیبت کے کر لیں اور لمز کے معنے عیب چینی کے کئے جائیں.یہ فرق میں نے کیوں کیا ہے؟ یعنی میں کیوں کہتا ہوں کہ ھمز کے معنے مارنے پیٹنے کے ہیں اور لمز کے معنے عیب چینی کے ہیں یا ھمز کے معنے غیبت کے ہیں اور لمز کے معنے عیب چینی کے ہیں.اس کی وجہ یہ ہے کہ فصیح کلام میں ہمیشہ تدریج پائی جاتی ہے اور یہ تدریج کبھی اقسام کے لحاظ سے ہوتی ہے اور کبھی ڈگری کے لحاظ سے.مثلاً ایک ادیب شخص اگر کسی کے متعلق یہ بیان کرنا چاہے گا کہ وہ کافی بوجھ اٹھا سکتا ہے تو وہ کہے گا کہ فلاں شخص ایک من بوجھ اٹھا سکتا ہے بلکہ دو من بھی اٹھا سکتا ہے.لیکن جو ادیب نہیں وہ کہے گا کہ فلاں شخص دو من بوجھ اٹھا سکتا ہے بلکہ ایک من بھی اٹھا سکتا ہے.ہر شخص جو اس فقرہ کو سنے گا یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ فقرہ فصاحت سے گرا ہوا ہے کیونکہ جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں شخص د و من بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اسے علیحدہ طور پر
Page 264
یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایک من بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے کیونکہ ایک من بوجھ دومن بوجھ میں شامل تھا.اسی طرح کوئی سمجھدار انسان یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص بڑا کام بھی کرسکتا ہے اور چھوٹابھی.یا ایم اے پاس بھی ہے اور بی اے بھی.ہاں یہ ضرور کہے گا کہ فلاں شخص بی اے پاس ہے بلکہ ایم اے بھی پاس ہے یا فلاں بات کی مقدرت رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فلاں بات کے کرنے کی بھی اس میں اہلیت پائی جاتی ہے.یا ادیب ہے بلکہ شاعر بھی ہے.مگر پہلے بڑی بات بیان کی جائے اور پھر چھوٹی.یہ فصیح کلام کے بالکل منافی ہوتاہے.ا س نقطۂ نگاہ کے ماتحت اگر ھمز ولمز میں سے ایک کے معنے ہم غیبت کے کرلیں اور دوسرے کے معنے منہ پر عیب چینی کے کرلئے جائیں تو یہ بالکل درست ہوں گے کیونکہ ان معانی میں تدریج پائی جائے گی جو ہر فصیح کلام کی ایک ممتاز خوبی ہوتی ہے.جو شخص غیبت کرنے کا عادی ہوتا ہے اس میں بہادری نہیں ہوتی.کچھ نہ کچھ ڈر اس کی طبیعت میں پایا جاتا ہے.گو عیب چینی کرنے کے لحاظ سے دونوں گناہ گار ہوتے ہیں وہ شخص بھی گناہ کرتا ہے جو کسی کی پیٹھ پیچھے عیب چینی کرتا ہے اور وہ شخص بھی گناہ کرتا ہے جو کسی کے منہ پر اس کے عیوب بیان کرنے شروع کردیتا ہے لیکن باوجود اس کے کہ وہ دونوں گناہ گار ہوتے ہیں پھر بھی ان میں ایک فرق پایا جاتا ہے.جس شخص میں بزدلی زیادہ ہوتی ہے وہ پیٹھ کے پیچھے عیب بیان کرتا ہے اور جو شخص شرارت میں بڑھ جاتا ہے وہ پیٹھ پیچھے بھی عیب چینی کرتاہے اور سامنے بھی کسی کا عیب بیان کرنے سے باز نہیں آتا.اس لحاظ سے ھمز اور لمز دونوں کے معانی میں ایک تدریج پائی جائے گی.ھمز سے وہ شخص مراد ہوگا جو غیبت کرتا ہے اور لمز سے وہ شخص مراد ہوگاجو غیبت ہی نہیں کرتا بلکہ منہ پر بھی گالیاں دینے لگ جا تا ہے.دوسری صورت میں نے یہ بتائی تھی کہ کبھی اقسام کے لحاظ سے بھی کلام میںتدریج پائی جاتی ہے.مگر اقسام سے میری مرادظاہری قسمیںنہیں بلکہ وہ قسمیںہیں جن کی علم ا لنفس پر بنیاد ہوتی ہے.مثلاً مار پیٹ بظاہر اعتراض کرنے سے زیادہ سخت نظر آتی ہے لیکن دوسری طرف ہمیںیہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ غصہ میں آکر انسان مار تو بیٹھتا ہے اور دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے لیکن سچائی کا انکار کرنا اس کے لئے بڑا مشکل ہوجاتا ہے.اب بظاہر سچائی کا انکار کم نظر آتا ہے اور مارپیٹ زیادہ سخت چیز دکھائی دیتی ہے لیکن علم النفس کے ماتحت مارپیٹ کم درجہ رکھتی ہے اور سچائی کا انکار بڑی خطرناک چیز ہے.مارنے کو تو مائیں بھی اپنے بچوں کو مارلیتی ہیں.باپ بھی اپنے بچوں کو مارلیتے ہیں.استاد بھی اپنے شاگردوں کو مارلیتے ہیں لیکن اگر انہی کو پوچھا جائے کہ بتائو تمہاری مارپیٹ زیادہ سخت ہے یا بچوں کا جھوٹ بولنا یا کسی اور برائی میں ان کا ملوث ہونا زیادہ خطرناک ہے؟ تو ہر شخص کہے گا کہ مارپیٹ اخلاقی خرابیوں کے
Page 265
مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی.اس تدریج کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ میں ھمز کے معنے مارپیٹ کے لئے جائیں گےا ور لمز کے معنی عیب چینی کے ہوں گے یعنی وہ لوگ نہ صرف مارتے پیٹتے ہیں بلکہ یہاں تک ان کی نوبت پہنچ چکی ہے کہ جن امور کی صداقت ان پر واضح ہوچکی ہے ان کا بھی انکار کرتے ہیں یعنی وہ تمام حُسن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ میں پایا جاتا ہے.وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پیدا فرمائی ہیں اور وہ تمام بھلائیاں جو اسلامی تعلیم میںرکھی گئی ہیں.ان میں سے ایک ایک حُسن اور ایک ایک خوبی اور ایک ایک بھلائی کا وہ بڑی سختی سے انکار کررہے ہیں.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐکے صحابہؓ سچی باتیں کہتے ہیں تو ان کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے.وہ انصاف قائم کرتے ہیں تو ان کو ظالم کہا جاتا ہے.وہ امن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو فسادی بتایا جاتا ہے.غرض کوئی خوبی اور بھلائی ایسی نہیں جس کا کفار کی طرف سے انکار نہ کیا جارہا ہو اور یہ حالت یقیناً ایسی ہے جو پہلی حالت سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ مارپیٹ میں تو صرف غصہ کا اظہار ہوتا ہے لیکن کسی سچائی کا انکار یا طعنہ زنی یا دوسروں کی تحقیر و تذلیل کا ارتکاب ایسے امور ہیں جو اخلاق اور روحانیت کے کلی فقدان پر دلالت کرتے ہیں اور جن کے اثرات بہت دیرپا ہوتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زخم مندمل ہوجاتے ہیں مگر وہ زخم جو زبان کی چھری دوسروں کے قلب پر پید اکرتی ہے کبھی مندمل نہیں ہوتے.غرض مارپیٹ کی نسبت طعنہ زنی اور تحقیر و تذلیل کے کلمات جو دوسروں کے متعلق استعمال کئے جائیں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں.پس ھمز کے معنے مارنے پیٹنے کے ہیں اور لمز کے معنے تحقیر و تذلیل اور سچائیوں کا انکار کرنے کے ہیں.بظاہر مارپیٹ زیادہ سخت نظر آتی ہے لیکن علم النفس کے ماتحت مارپیٹ کم درجہ رکھتی ہے اور سچائی کا انکار زیادہ خطرناک ہوتا ہے.یہی حکمت ہے جس کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ھمز کو پہلے رکھا اور لمز جس میں اخلاقی برائی زیادہ تھی اس کا بعدمیں بیان کیا.لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ھمز کو پہلے رکھ دیا اور لمز کو بعد میں.حالانکہ ھمز کو پہلے ہی رکھنا چاہیے تھا اور لمز کو بعد میں ہی رکھنا چاہیے تھا.اگر لمز کو پہلے اور ھمز کو بعد میں رکھا جاتا تو کلام اپنی فصاحت کھو بیٹھتا.یہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے جہاں بھی کسی لفظ کو استعمال کیا ہے موقع اور محل کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے استعمال کیا ہے.اگر اس لفظ کو ذرا بھی ادھر ادھر کردیا جائے تو بہت بڑا نقص واقع ہوجاتا ہے.اس سورۃ میں گو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے.لیکن اس سے ایک عام قاعدہ کا بھی استنباط ہوتا ہے.قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ ایسے رنگ میں بات کرتا ہے کہ ہر زمانہ کے
Page 266
لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ یہ بات میرے متعلق نہیں بلکہ کسی گذشتہ زمانہ کے لوگوں کے متعلق ہے.بعض نے لکھا ہے کہ ھمز اور لمزمیں مغیرہ،عاص بن وائل اور شریک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.چونکہ یہ لوگ اسلام کے خلاف ہمیشہ ناجائز حرکات کیا کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کے ذریعہ ان کو انتباہ فرما دیا کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو ان پر عذاب نازل کردیا جائے گا.مگر میرے نزدیک کوئی وجہ نہیں کہ اس سورۃ کے وسیع مضمون کو اس طرح محدود کرنے کی کوشش کی جائے.اگر یہ سورۃ محض مغیرہ کے کسی فعل کی وجہ سے نازل ہوئی تھی یا صرف عاص بن وائل کو اس میں مخاطب کیا گیا تھا یا صرف شریک کا اس میںذکر تھاتو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وَیْـلٌ لِّــعَــاصِ بْـنِ وَائِلٍ یا وَیْلٌ لِّمُغِیْـرَۃَ یا وَیْلٌ لِّشَـرَیْکٍ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بلکہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ کہا ہے.اس میں حکمت یہ ہے کہ کلام میں جب کسی خاص شخص کی تعیین کر دی جائے تومضمون نا مکمل ہو جاتا ہے مثلا اگر ہم کہیں وَیْلٌ لِّزَیْدٍ زید کے لئے ہلاکت ہے تو ہر شخص یہ دریا فت کرنے کی کوشش کرے گا کہ زید کیوں برا ہے یا اس میں کون سی خرابی پائی جاتی ہے کہ اس کے متعلق وَیْل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے.لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ تو ہر شخص کہے گا کہ یہ با کل درست ہے جو غیبت کرتا ہے یا جسے عیب چینی کی عادت ہے یا سچائیوں کا انکار کرتا ہے وہ ضرور برا ہے اور اس قابل ہے کہ اس کو سزا ملے.دوسرے قرآن کریم چونکہ ہر زمانہ کے لوگوں کی ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ایک مکمل دستور العمل قرار دیا ہے اس لئے اگر اس سورۃ میںکسی کا نام لے لیا جاتا تواس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا.مثلا اگر یہ کہا جاتا کہ وَیْلٌ لِّعَاصِ بْنِ وَائِلٍ تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا تھا وہ مر گیا اس کی اولاد بھی مر گئی.اولاد کی اولاد بھی مر گئی اور پھر اس اولاد کی اولاد بھی مر گئی.بلکہ اس کی اولاد بعد میں مسلمان بھی ہو گئی اور اسلام کی خدمت میں اس نے اپنی عمر بسر کر دی.اب ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا کہ وَیْلٌ لِّعَاصِ بْنِ وَائِلٍ یا وَیْلٌ لِّمُغِیْـرَۃَ یا وَیْلٌ لِّشَـرَیْکٍ لیکن جب یہ کہا گیا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ تو قیامت تک ہر شخص کو فا ئدہ پہنچ سکتاہے اور ہر شخص کوشش کرے گا کہ میں ھمزہ لمزہ نہ بنوں.پس چونکہ قرآن کریم ایک دائمی شریعت ہے جس میں ہر زمانہ کے لوگوں کی اصلاح کا سامان رکھا گیا ہے اس لئے قرآن کریم وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو قیامت تک کام آنے والے ہوںاور جن سے ہر زمانہ کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہوں.پس اگر بعض اشخاص کے نام لے لئے جاتے تو اس کلام کا فائدہ اسی زمانہ میں ختم ہو جاتا اور ہمارے لئے یہ آیات محض ایک گذشتہ تا ریخ کا ورق بن جاتیں.ہم سمجھتے کہ کوئی عاص بن وائل تھا جس پر عذاب آیا یا کوئی مغیرہ تھا جس
Page 267
میں فلاں فلاں خرابیاں پائی جا تی تھیں یا کوئی شریک تھا جو اس قسم کی عادات رکھتا تھا.چنانچہ جب ہم اس سورۃ پر پہنچتے فوراً کہہ اٹھتے کہ ہمیں اس سے کیا غرض یہ ایک پرانا واقعہ بیان کیا جارہا ہے ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں.لیکن اب ہم ایسا نہیں کہہ سکتے.اب ہر شخص مجبور ہے کہ ان آیات کو پڑھے اور مجبور ہے اس امر پر کہ وہ ہمزہ اور لمزہ نہ بنے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد نہ بن جائے.پس خواہ یہ آیات مغیرہ کے متعلق ہوں یا عاص بن وائل کے متعلق یا شریک کے متعلق.اللہ تعا لیٰ نے اس سورۃ میںشخصی بحث نہیں کی بلکہ فلسفیانہ بحث کی ہے اگر شخصی بحث کی جاتی تو یہ کلام متروک ہو جاتا لیکن فلسفیانہ بحث کی وجہ سے پہلے بھی یہ کلام بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتا رہا ہے، اب بھی پہنچا رہا ہے اور آئندہ بھی پہنچاتا رہے گا اور جس شخص میں بھی یہ باتیں پائی جائیں گی اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کروںایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن جائوں.بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ہر شخص جو دوسروں کو کچل کر آپ بڑا بننا چاہتا ہے یا دوسروں کی عیب چینی میں مشغول رہتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ان حرکات سے باز نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو گا.اس صورت میں لمز کے معنے تو عیب چینی کے ہوں گے.ھمز کے معنے متکبر اور مغرور انسان کے ہوں گے کیونکہ مار پیٹ ہمیشہ مغرور انسان کا شیوہ ہوتا ہے اور اس کی غرض اس قسم کے ظالمانہ سلوک سے یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو کچل دے اور اس پر اپنی طاقت کا اظہار کرے.دوسری صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ اپنی نعمتوں کو کھو بیٹھے گا اور سخت حسرت اور افسوس کرے گا.ہر وہ شخص جو دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے بلکہ غیبت پر ہی منحصر نہیںمنہ پر بھی دوسروں کے عیوب بیان کر دیتا ہے اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بھی بول رہا ہوںاور دوسرے کا دل بھی دکھا رہا ہوں.غیبت کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی سچا عیب اس کی عدم موجودگی میں بیان کیا جائے تو وہ غیبت میں داخل نہیں ہوتا ہاں اگر جھوٹی بات بیان کی جائے تو وہ غیبت ہوتی ہے حالانکہ یہ صحیح نہیںغیبت کا اطلاق ہمیشہ ایسی سچی بات پر ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو بدنام کرنے کے لئے اس کی غیر حاضری میں بیان کی جائے اگر جھوٹی بات بیان کی جائے گی تو وہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہوگا.احادیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ غیبت تو بری چیز ہوئی اگر اپنے بھائی کا کوئی سچا عیب اس کی عدم موجودگی میں بیان کیا جائے تو آیا یہ تو منع نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی عدم موجودگی میں اس کا سچا عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے ورنہ اگر دوسرے کے متعلق جھوٹی بات بیان کی جائے تو یہ بہتان بن
Page 268
جائے گا.(مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب باب تـحریم الغیبۃ ) اسلام نے غیبت کی ممانعت کے متعلق جو حکم دیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان دوسرے کے متعلق ایک رائے قائم کر تا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس رائے میں حق بجانب بھی سمجھتا ہے لیکن در حقیقت اس کی رائے صحیح نہیں ہوتی.ہم نے بیسیوں دفعہ دیکھا ہے کہ ایک شخص دوسرے کے متعلق ایک قطعی رائے قائم کر لیتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میری رائے درست ہے لیکن ہوتی غلط ہے.ایسی صورت میںاگر دوسرا شخص سامنے بیٹھا ہوگا اور اس کے متعلق کسی رائے کا اظہار کیا جائے گا تو لازماً وہ اپنی برأت کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے میرے اندر یہ نقص نہیں پایاجاتا.پس خواہ کسی کے نزدیک کوئی بات سچی ہو جب وہ دوسرے شخص کی عدم موجودگی میں بیان کرتا ہے اور وہ بات ایسی ہے جس سے اس کے بھائی کی عزت کی تنقیص ہوتی ہے یا اس کے علم کی تنقیص ہوتی ہے یا اس کے رتبہ کی تنقیص ہوتی ہے تو قرآن کریم اور احادیث کی رو سے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو اپنی برأت پیش کرنے کے حق سے محروم کر دیا ہے.چونکہ یہ سورۃ گذشتہ ترتیب کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق ہے اس لئے اس سورۃ میں اس زمانہ کے کفار کا حال بتایا گیا ہے کہ ان کا رات دن یہ کام رہتا تھا کہ مسلمانوں کو مارتے ان کو مصائب اور تکالیف میںمبتلا کرتے اور ان پر قسم قسم کے مظالم توڑتے پھر اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی شیوہ تھا کہ وہ ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے یعنی صرف خود ہی ان کے دشمن نہیں تھے بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دوسرے لوگ بھی ان کے دشمن بن جائیں.آخر کسی کا عیب بیان کرنے کی کیا غرض ہوتی ہے یہی کہ دوسروں کو بھی برانگیختہ کیا جائے.پس ھمز کے لحاظ سے تو ان کی یہ حالت تھی کہ وہ مسلمانوں کو مارتے اور ان کو مختلف قسم کے مصائب میں مبتلا کرتے.لیکن لمز کے لحاظ سے وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ باقی دنیا کو بھی مسلمانوں کا دشمن بنا دیں کفار کی ان شرمناک حرکات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ وہ تمام اشخاص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کو دکھ دیتے اور دوسری طرف ان کے خلاف ہر وقت پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں اور اس طرح پبلک کو بھی اسلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیںانہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسا عذاب نازل ہونے والا ہے جس سے ان کے دلوں کا چین بالکل اڑ جائے گا اور ان کی امیدیں سب خاک میں مل جائیں گے.
Page 269
ا۟لَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗۙ۰۰۳ جو مال کو جمع کرتا اور اس کو شمار کرتا رہتا ہے.حلّ لُغات.عَدَّدَ.عَدَّدَ الْمَالَ جَعَلَہٗ عُدَّۃً لِلدَّھْرِ یعنی جب عَدَّدَ الْمَالَ کہا جائے تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیںکہ اس نے مصیبت کے دنوں میںکام آنے کے لئے اپنا مال جمع کیا (اقرب) دنیا میں جب کوئی شخص اپنی ذاتی ضروریات کے لئے مثلا شادی بیاہ کے لئے یا بیماریوں اور مقدمات وغیرہ کے لئے کچھ روپیہ پس انداز کرتا ہے تو اس مال کو عُدَّۃ کہتے ہیںپس جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ کے معنے یہ ہوں گے کہ اس نے روپیہ جمع کیا اور پھر یہ خیال کیا کہ یہ روپیہ میری مصیبت کے وقت کام آئے گا یا دشمن کے حملوں سے میری حفاظت کا ذریعہ ثابت ہوگا یا اور ضروریات کو پورا کرنے کا موجب ہوگا.پھر عَدَّدَ کے معنے گننے کے بھی ہوتے ہیںلیکن عام طور پر عربی زبان میں جب عَدَّدَ کا لفظ گننے کے لئے آئے تو متعدد چیزوں کے لئے آتا ہے(اقرب).مثلاً کہا جائے گا عَدَّدَ الدَّرَاھِمَ.اس نے دراہم گنے کیونکہ دراہم متعدد ہوتے ہیں.لیکن عَدَّدَ الْمَالَ کہیں تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ اس نے اپنا مال کسی ضرورت کے لئے سنبھال کر رکھا.گننے کے معنے اس میںنہیں پائے جائیں گے.ہاں اگر مال کو کلیکٹوٹرم قرار دیا جائے یعنی ایسی چیز جو ہوتی تو ایک ہے مگر دلالت تعدد پر کرتی ہے تو اس لحاظ سے اس کے معنے گننے کے بھی ہوسکتے ہیںاور جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ سخت لالچی اور حریص ہے.ایک طرف مال جمع کرتا ہے اور دوسری طرف اس کو ہمیشہ گنتا رہتا ہے کہ میرے پاس آج اتنا روپیہ جمع ہو گیا ہے کل اتنے روپے جمع ہو جائیں گے.اسی طرح عَدَّدَ کا لفظ بعض دفعہ کسی چیز کے اوصاف بیان کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ عربی میں کہتے ہیں عَدَّدَ الْمَیِّتَ اس نے میّت کو گنا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ عَدَّ مَنَاقِبَہٗ اس نے میّت کے مناقب بیان کئے(اقرب) اور کہا کہ وہ بڑا سخی تھا، بڑا بہادر تھا یا بڑا سمجھدار تھا.چونکہ اخلاق کئی ہوتے ہیںاس لئے مختلف صفات اور عادات کے لحاظ سے بھی عَدَّدَ کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے.اس صورت میں جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور پھر اس کی خوبیاں بیان کرنی شروع کر دیتا ہے کہ اگر مال کو روک کر رکھا جائے اور ان لوگوںکی تقلید نہ کی جائے جو ضروریات کے پیش آنے پر فوراً روپیہ خرچ کر دیا کرتے ہیںتو اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں.اصل قرأت تو عَدَّدَهٗ ہی ہے لیکن بعض قراء نے اس کو عَدَدَهٗ بھی پڑھا ہے.
Page 270
تفسیر.عام محاورہ کے مطابق اس آیت میں جَـمَعَ الْمَالَ کے الفاظ ہونے چاہیے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے جَـمَعَ الْمَالَ کی بجائے جَـمَعَ مَالًا فرمایا ہے.اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے اور مَالًا کی تنوین اپنے اندر کیاحکمت رکھتی ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تنوین اپنے اندر تین حکمتیں رکھتی ہے.اوّل.یہ تنوین تحقیر کی بھی ہو سکتی ہے.دوم.یہ تنوین تقبیح کی بھی ہو سکتی ہے.سوم.یہ تنوین تعظیم کی بھی ہو سکتی ہے.پہلی صورت میں الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا کے یہ معنے ہو ں گے کہ جس نے تھوڑا سا مال جمع کیا اور پھر اس پر فخر کرنے لگا.یہاں تھوڑے مال کا یہ مفہوم نہیں کہ اس نے کم روپیہ جمع کیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال خواہ کسی نے ڈھیروں ڈھیر جمع کر لیا ہو بہر حال ایک فانی متاع ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی دین اور اس کے بدلہ کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا.اسی وجہ سے قرآن کریم میں دنیا کے اموال کے متعلق یہ صرا حتاً فرمایا گیا ہے کہ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ (التوبۃ:۳۹) دنیا کی متاع آخرت کے مقابلہ میں نہایت قلیل چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواہ ساری دنیا کا مالک بن جائے بہرحال چالیس پچاس سال کے بعد مر جاتا ہے اور پھر اس لحاظ سے بھی متاع الحیٰوۃ قلیل ہے کہ انسان نے مر کر اگلے جہان جانا ہے اگر کسی انسان نے اس مقام پر اپنے لئے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا تو دنیا کے اموال اسے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیںاور اگر کسی انسان نے اس جگہ اپنے لئے سرمایہ جمع کیا ہوا ہے تب بھی اس کے مقابلہ میںدنیا کا مال کوئی حقیقت نہیں رکھتا غرض کوئی نقطۂ نگاہ لے لو بہر حال دنیا کا متاع قلیل ہے.پس جَمَعَ مَالًا کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ جَـمَعَ مَالًا قَلِیْلًا.اس نے دنیا کی تھوڑی سی پونجی جمع کر لی اور پھر اس پر گھمنڈ شروع کر دیا کہ میں بڑا مال دار بن گیا ہوں.(۲) تقبیح کی صورت میں اس کے یہ معنے ہوں گے کہ اَلَّذِیْ جَـمَعَ مَالًا حَرَامًا.ایسا مال اس نے جمع کیا جو نہایت ردی اور خبیث تھا.حالانکہ عقلمند انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی گندی چیز ملے تو اسے اٹھا کر پھینک دے نہ یہ کہ اسے حفاظت کے ساتھ اپنے گھر لے آئے.اگر کسی کو کوئی کھوٹا سکہ مل جائے تو وہ اسے اٹھا کر اپنی جیب میں نہیں رکھ لیتا یا اسے نجاست سے لتھڑی ہوئی کوئی چیز مل جائے تو وہ اسے اپنے گھر میں نہیں لے آتا مگر ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ مال اپنے پاس رکھتے ہیں جو گندہ ہے اور جسے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اکٹھا کیا گیا ہے حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ایسا مال فوراََپھینک دیتے اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس کو اپنے پاس رکھنے کے لئے تیار نہ ہوتے.
Page 271
(۳) تعظیم کی صورت میں اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ اَلَّذِیْ جَـمَعَ مَالًا کَثِیْـرًا.جس نے بہت سا مال جمع کیا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں لاکھوں روپیہ بھی بالکل حقیر چیز ہے لیکن بندہ جب اپنی نگاہ سے اس مال کو دیکھتا ہے تو اسے بہت بڑا مال معلوم ہوتا ہے اگر کسی کے پاس ہزار روپے بھی جمع ہوجائیںتووہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس بہت روپیہ جمع ہوگیا ہے.حالانکہ ہزار روپیہ موجودہ زمانہ میں کوئی حقیقت ہی نہیںرکھتا.وہ مفسرین جنہوں نے ان آیات کو کفارمکہ پر چسپاں کیا ہے انہوں نے الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا کے ماتحت لکھا ہے کہ شریک کے پاس پندرہ ہزار درہم تھے جن کی وجہ سے وہ دوسروں پر فخر کا اظہار کیا کرتا تھا(بحر محیط سورۃ الھمزۃ زیر آیت الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ).پندرہ ہزار درہم آج کل کے حساب سے صرف پانچ ہزار روپے بنتے ہیںاور یہ روپیہ موجودہ زمانہ کی دولت کے لحاظ سے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا.ہندوستان میں ہی اگر کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ بڑا مال دار ہے اس کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں تو سب لوگ ہنس پڑیں گے کہ کیسی احمقانہ بات کہی گئی ہے پانچ ہزار روپے بھی کوئی چیز ہیں.مگر عرب میں یہ بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی اور اگر کسی کے پاس اتنا روپیہ جمع ہو جاتا تو وہ خیال کیاکرتا تھا کہ اب مجھ سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے میرے پاس تو پانچ ہزار روپے جمع ہیں.لیکن موجوہ زمانہ میں دنیا کی امارت کا یہ حال ہے کہ ہندو ستان کے اکثر حصے ایسے ہیں جہاںصر ف اسی شخص کو مالدار سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دس پندرہ لاکھ روپے ہوں.لیکن اگر بمبئی چلے جائو تو وہاں دس پندرہ لاکھ والے کو کوئی شخص مالدار کہنے کے لئے تیار نہیں ہوگا وہاں اسّی نوّے لاکھ یا ایک کروڑ روپیہ رکھنے والے کو مالدار کہا جاتا ہے.اس کے بعد انگلستان چلے جائو تو وہاں ایک کروڑ روپیہ رکھنے والے کو کوئی شخص مالدار نہیں کہے گا وہاں دس پندرہ کروڑ رکھنے والے کو مالدار سمجھا جاتا ہے پھر امریکہ چلے جائو تو وہاں دس پندرہ کروڑ والے کو کوئی شخص مالدار نہیں کہتا وہاں ڈیڑھ دو کروڑ یا اس سے بھی زیادہ سالانہ انکم رکھنے والے کو مالدار سمجھا جاتا ہے.غرض امارت کا معیار موجودہ زمانہ میں بہت بلند ہو گیا ہے.لیکن عربوں کے لئے یہی بات بڑی تھی کہ ان میں سے کسی کے پاس پانچ چھ ہزار روپیہ جمع ہو گیا.پس جَمَعَ مَالًا میںتنوین تعظیم کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس صورت میں یہ تعظیم اس انسان یا اس قوم کے نقطہ نگاہ سے ہو گی جس نے مال جمع کیا ہے اور آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑا مال جمع کر لیا ہے.بہر حال اس آیت کے تینوں معنے ہوسکتے ہیں.یہ معنے بھی ہو سکتے ہیںکہ اس نے بہت سا مال جمع کیا ہے، یہ معنے بھی ہوسکتے ہیں کہ اس نےمعمولی سا مال جمع کیا ہے اور یہ معنے بھی ہو سکتے ہیںکہ اس نے گندہ اور ردی مال جمع کیا ہے.عَدَّدَهٗ.عَدَّدَ کے معنے جو اوپر بیان کئے گئے ہیںوہ سب کے سب ا س مقام پر چسپاں ہوتے ہیںچنانچہ
Page 272
دنیا میںجس قدر بخیل لوگ پائے جاتے ہیںان سب میں یہ نقص ہوتا ہے کہ وہ روپیہ جمع کرتے ہیںاور پھر ہمیشہ گنتے رہتے ہیںکہ اب ہمارے پاس اتنے روپے ہو گئے ہیںاب ہزار روپیہ ہو گیا ہے، اب لاکھ روپیہ ہو گیا ہے، اب کروڑ روپیہ ہوگیا ہے.انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اگر اس مال کو کسی نفع مند کام پر لگا یا جاتا یا بنی نوع انسان کی بھلائی کے کاموں پر صرف کیا جاتا تو کیسا اچھا ہوتا اور کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا.پھر یہ بھی ایک عام مرض بخیل لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ روپیہ تو جمع کرتے ہیںمگر قومی ضروریات تو الگ رہیں اپنی ذاتی ضروریات پر بھی اس کو خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے.بخیل کی بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ تم روپیہ کیوں خرچ نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے کہ یہ روپیہ تو کسی دن کے لئے رکھا ہوا ہے پہلے ہی اس کو کس طرح خرچ کر دوں.مگر اس کی ساری عمر گذر جاتی ہے اور اس کا وہ دن کبھی نہیں آتا.روپیہ غلق میں ہی بند رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے.بعد میں اس کی اولاد شراب اور جوئے میں اس کے روپیہ کو برباد کر دیتی ہے یا کنچنیوںکے ناچ گانے میں سب جائدادلٹا دیتی ہے.لیکن اس کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بیمار ہو،اس کی بیوی بیمار ہو،اس کا بچہ بیمار ہو،اس کا بھائی بیمار ہو،اور اسے کہا جائے کہ علاج کرائو تو کہتا ہے یہ روپیہ تو کسی دن کے لئے رکھا ہوا ہے.اسی طرح اس کی ساری عمر کٹ جاتی ہے.وہ ننگا رہتا ہے،وہ بھوکا رہتا ہے،وہ بیمار رہتا ہے،وہ مصائب میں مبتلا رہتا ہے،اس کے بیوی بچے تکالیف اٹھاتے ہیںمگر اس کا وہ دن نہیں آتا جس کے لئے اس نے روپیہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے.تیسرے معنے اس کے یہ ہیںکہ بجائے اس کے کہ وہ مال خرچ کرے اور پبلک کو روپیہ کے چکر سے فائدہ پہنچے وہ اپنے اس فعل کی خوبیاںبیان کرتا رہتا ہے اور دوسروں سے بھی یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ روپیہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اس کا یہ یہ فائدہ ہوتا ہے.یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس فعل پر نادم اور شرمندہ ہو وہ فخر کرتا ہے اور دوسروں سے بھی یہی کہتا ہے کہ روپیہ کی انسان کو اپنی زندگی میں بڑی ضرورت پیش آتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ذاتی یا قومی ضروریات کو نظر انداز کر دیا کرے گویا نادم اور شرمندہ ہونے کی بجائے وہ الٹا گناہ پر فخر کرتا ہے.يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗۚ۰۰۴ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس(کے نام) کو باقی رکھے گا تفسیر.يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ.اس آیت میںیہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ روپیہ خرچ کرنے میں
Page 273
بخل سے کیوں کام لیا جاتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ.وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی بقا کا باعث ہو گا یعنی مالدار لوگوں میںبخل کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میںیہ احساس ہوتا ہے کہ جمع کیا ہوا مال ہمارے خاندان کی عزت کا موجب ہوگا.اسی وجہ سے وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں مگر روپیہ خرچ نہیں کرتے.ایک ادنیٰ بخیل کے ذہن میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ میں آج سے دس سال کے بعد اپنے بیٹے کی شادی پر یا اپنے مکان کی تعمیرپر روپیہ خرچ کروں گا مگر بڑے بخیل کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی.وہ چاہتا ہے کہ میں بھی روپیہ جمع رکھوں میری اولاد بھی روپیہ جمع کرتی جائے اور اس کی اولاد بھی روپیہ جمع کرتی جائے تاکہ ہمارے خاندان کا نام اور اس کی شہرت قائم رہے.وہ سمجھتا ہے کہ مال رہنے کی وجہ سے ہمارے خاندان کو دائمی عزت حاصل ہوجائے گی.حالانکہ اگر وہ سوچے تو اسے روزانہ یہ نظارے نظر آسکتے ہیں کہ ایک شخص بڑی مشکل سے روپیہ جمع کرتا ہے وہ خود بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، ننگا رہتا ہے، بیمار رہتا ہے مگر روپیہ خرچ نہیں کرتا.چاہتا ہے کہ اس کے پاس کافی مال جمع ہوجائے مگر جب مر جاتا ہے تو اس کی اولاد تمام روپیہ عیاشی میں برباد کردیتی ہے.حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ چونکہ مہاراجہ جموں کے شاہی طبیب تھے اس لئے ریاست کے کئی مالدار لوگوں سے آپ کے تعلقات رہا کرتے تھے.آپ فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ ایک بڑا مالدار شخص مرگیا تو تھوڑے دنوں کے بعد ہی مجھے ایک شخص نے آکر کہا کہ اس کے بیٹے نے عجیب طرح روپیہ لٹانا شروع کردیا ہے.میں نے کہا کس طرحـ؟ وہ کہنے لگا ایک دن وہ بازار میں سے گذر رہا تھا کہ اس نے ایک بزاز کو تھان میں سے کچھ کپڑا پھاڑتے دیکھا جس میں سے چر کی آواز پید اہوئی.یہ آواز اسے ایسی پسند آئی کہ اب اس کا دن رات یہی کام ہے کہ وہ بازار سے کپڑے کے تھان منگواتا ہے اور اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ میرے سامنے انہیں صبح سے شام تک پھاڑتے رہو.کیونکہ کپڑے کے پھاڑنے سے جو چر کی آواز نکلتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے.حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اسے بلا کر سمجھایا اور کہا کہ اس طرح روپیہ برباد مت کرو یہ بالکل لغو طریق ہے.اس نے جواب دیا مولوی صاحب جو مزا اس چر میں ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں.تم اسے دماغ کی خرابی کہہ لو مگر آخر ہوا کیا؟ یہی کہ باپ نے جو روپیہ جمع کیا تھا وہ سب برباد ہوگیا.باپ نے نامعلوم کن کن مصیبتوں سے روپیہ جمع کیا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے دماغ میں ایسی خرابی پیدا کردی کہ اس نے تما م روپیہ برباد کردیا.اسی طرح ایسے ایسے بخیل بنیئے جو ساری عمر دال سے بھی روٹی نہیں کھاتے اور روپیہ جمع کرتے رہتے ہیں ان کی اولادیں جوئے اور سٹہ میں سب روپیہ برباد کردیتی ہیں.پس فرماتا ہے يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ.وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ قائم رکھے گا.حالانکہ مال قائم نہیں رکھتا
Page 274
بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل قائم رکھتا ہے.حضرت دائود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کسی نیک آدمی کی اولاد کو سات پشت تک فاقہ کرتے اور بھیک مانگتے نہیں دیکھا(زبور باب ۳۷ آیت ۲۵ ).حالانکہ کئی کروڑ پتی ایسے ہوتے ہیں جن کی اولادیں اپنی زندگی کے دن فاقوں میں بسر کردیتی ہیں.پس خدا تعالیٰ سے تعلق ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو خلود بخشتا ہے.جو شخص انفاق فی سبیل اللہ سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال کو بے دریغ خرچ کرتا رہتا ہے وہی شخص ہے جس کا مال اس کی بقاء کا باعث ہوتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہؓ سے فرمایا بتائو کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جسے اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ ہو.صحابہؓ نے عرض کیا یارسول اللہ یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ ہمیں اپنے مال سے اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو.ہمیں تو وہی مال پسند ہوتا ہے جو ہمارا اپنا ہو.آپؐنے فرمایا تو پھر یاد رکھو تمہارا مال وہی ہے جسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو.ورنہ جو کچھ تمہارے مال میں سے باقی رہ جاتا ہے وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے ورثاء کا ہے کیونکہ تمہاری آنکھ کے بند ہوتے ہی اس پر قبضہ کرلیا جاتا ہے (بخاری کتاب الرقاق باب ما قدم من مالہ فھو لہ).یہ حدیث اسی مضمون کو بیان کرتی ہے کہ مال وہی کام آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو.کیونکہ دوسرا مال تو غیروں کے کام آتا ہے اور یہ مال انسان کے اپنے کام آتا ہے.اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شخص جنت میں جاتا ہے اور کوئی دوزخ میں.اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ہوا ہوتا ہے اسے بہت بڑا اجر ملتا ہے.تب بھی اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اگر قومی ضروریات پر روپیہ خرچ کیا جائے تو انسان کا نیک نام باقی رہ جاتا ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شخص قوم کا بڑا خادم تھا یا غرباء کا بڑا ہمدرد تھا یا یتامیٰ و بیوگان کا بہت خیال رکھنے والا تھا.لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں کہ لوگ ایک طرف تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے کے مال سے انہیں اپنا مال زیادہ پیارا ہوتا ہے مگر عملاً وہ یہ کررہے ہوتے ہیں کہ وہ مال جو انہوں نے اپنے ساتھ لے جانا ہوتا ہے یا جس نے ان کی نیک نامی کا موجب بننا ہوتا ہے اس سے تو وہ پیار نہیں کرتے اور جو مال دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے اس سے وہ پیار کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی یا قومی ضروریات پر روپیہ خرچ کرنے کی بجائے اسے جمع رکھا جائے.حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہی انسان کو خلود بخشتا ہے.جمع کیا ہوا مال خلود نہیں بخشتا.
Page 275
كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِٞۖ۰۰۵ ہرگز ایسا نہیں (جیسا اس کا خیال ہے بلکہ) وہ یقیناً (اپنے مال سمیت) حطمہ میں پھینکا جائے گا.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُؕ۰۰۶ اور (اے مخاطب) تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ حطمہ کیا شے ہے.نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُۙ۰۰۷ یہ (حطمہ) اللہ تعالیٰ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِؕ۰۰۸ جو دلوں کے اندر تک جا پہنچے گی.حلّ لُغات.حُطَمَۃ.حُطَمَۃ کے معنے عربی زبان میں توڑنے کے بھی ہوتے ہیں اور حُطَمَۃ کے معنے آگ کے بھی ہوتے ہیں.چنانچہ لغت میں لکھا ہے حَطَمَہٗ: کَسَـرَہُ.الْـحُطَمَۃُ: اَلنَّارُ الشَّدِیْدَۃُ (منجد) پس حُطَمَہ کے معنے ہوئے توڑنے والی یا حُطَمَۃ کے معنے ہوئے ایسی آگ جو سخت بھڑکنے والی ہے.تفسیر.اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار کو ان کا انجام بتاتا ہے کہ اس وقت تو ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مسلمانوں کو مارتے اور دکھ دیتے ہیں.اسی طرح مال کے گھمنڈ میں وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی ہمارے مقابلہ میں حیثیت ہی کیا ہے.یہ ذلیل اور ادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں یا جب مسلمان روپیہ خرچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نیک نامی چاہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں توکہتے ہیں دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں توکہتے ہیں نام و نمود کے لئے ایسا کرتے ہیں.غرض ان کے ہر نیک کام کو برے رنگ میں پیش کرتے ہیں.لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جس مقام پر وہ کھڑے ہیں وہ کوئی عزت بخشنے والا نہیں.فرماتا ہے کَلَّا دشمن اس خیال میں نہ رہے کہ جس مقام پر مسلمان کھڑے ہیں وہ تباہی و بربادی کی طرف لے جانے والا ہے اور جس مقام پر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ قائم رہنے والا ہے لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وہ ایک بھڑکنے والی آگ میں ڈالا جائے گا.یہ بھڑکنے والی آگ کیا ہے؟ مفسرین نے اپنی عادت کے مطابق
Page 276
اسے قیامت پر چسپاں کیا ہے.لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ سے مراد دنیا میں عذاب کا شکار ہونا ہے وہ کہتے ہیں کہ لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے.مگر میرے نزدیک چونکہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لئے دنیوی عذاب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی شدت کے لحاظ سے دوزخ کا عذاب کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں.اس لئے حُطَمَۃ سے یہاں دنیا کی آگ مراد ہے اوراگر اس کے معنے توڑنے کے لئے جائیں تب بھی اس کے یہ معنے ہوں گے کہ ہم ان کی شوکت کو بالکل توڑ پھوڑ دیں گے.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ.قرآن کریم میں جہاں بھی مَاۤ اَدْرٰىكَ کے الفاظ آتے ہیں وہاں اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس مقام پر جو لفظ رکھا ہے وہ عربی زبان کے لحاظ سے کئی معنوں میں استعمال ہوسکتا ہے.لیکن ہمارے نزدیک اس لفظ کے یہاں فلاں معنے ہیں.علمِ طریق تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا لفظ آجائے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہو تو اس کے سارے معنے لئے جاسکتے ہیں.لیکن جب خدا تعالیٰ کا یہ منشا نہ ہو کہ سارے معنے لئے جائیں بلکہ یہ منشا ہو کہ صرف فلاں معنے لئے جائیں تو اس وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ مَاۤ اَدْرٰىكَ تجھے کس نے بتایا ہے کہ اس کے کیا معنے ہیں.یعنی اس لفظ کے کئی معنے ہوسکتے ہیں لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس مقا م پر ہمارے مدّ ِنظر کون سے معنے ہیں.نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ.فرماتا ہے یہاں حُطَمَۃ کے معنے اللہ تعالیٰ کی اس آگ کے ہیں جو خوب بھڑکائی گئی ہے.آگ دو قسم کی ہوتی ہے.ایک آگ وہ ہوتی ہے جسے بندے بھڑکاتے ہیں، وہ لکڑیاں جمع کرتے اور دیاسلائی سے آگ روشن کرتے ہیں اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جلاتا ہے.پھر اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ بھی دو قسم کی ہوتی ہے.ایک آگ تو اگلے جہان کی ہے جو دوزخ کی شکل میں ظاہر ہوگی اور ایک آگ ایسی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ہی بھڑکایا جاتا ہے اور یہی وہ آگ ہے جسے عذاب کہا جاتا ہے.پس نَارُ اللّٰهِ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار کے لئے اس دنیا میں مقدر تھا.لکڑی کی آگ پر پانی ڈالو تو وہ بجھ جاتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لئے کفار نے خوب آگ بھڑکائی مگر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیئے.ادھر آگ روشن ہوئی اور ادھر بارش برسنی شروع ہوگئی جس سے تمام آگ بجھ گئی.آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانے دو آج بارش نے ہماری آگ بجھادی ہے پھر کسی وقت ابراہیمؑ کو آگ میں ڈال دیں گے مگر کفر کا جوش چونکہ عارضی ہوتا ہے انہی میں سے کچھ لوگ بول پڑے کہ ابراہیم بھی تو ہمارے رشتہ داروں میں
Page 277
سے ہے اس کو جلانے کا کیا فائدہ ہے.چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعد میںدوبارہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش نہیں کی.پس بندوں کی جلائی ہوئی آگ بجھ سکتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جلائی ہوئی آگ سے سلامت نکال لیا لیکن خدا تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ میں سے کوئی شخص دوسرے کو نکال نہیں سکتا کیونکہ بسا اوقات دل میںآگ لگ رہی ہوتی ہے اور انسان کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اس آگ سے نکلوں مگر وہ نکل نہیں سکتا.چنانچہ اس آگ کی اللہ تعالیٰ نے خودہی آگے تشریح کردی ہے کہ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ہماری یہ آگ دلوں پر بھڑکائی گئی ہے لکڑیوں کی آگ نہیں کہ پانی سے بجھ سکے یہ دل کی آگ ہے جس کے شعلے ان کو ہر وقت بھسم کررہے ہیں.وہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل جلتے ہیں.غم واندوہ سے کباب ہوتے جاتے ہیں.حسرت و افسوس سے ان کی زندگیاں تلخ ہو رہی ہیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دکھ کا ہم کیا علاج کریں.ابو جہل کا دوانصاری لڑکوں کے ہاتھوں قتل بدر کے موقع پر جب ابوجہل اپنے لشکر سمیت نکلا تو اس کو یہ خیال تک نہیں تھا کہ مسلمانوں سے ہماری جنگ ہونے والی ہے.خود مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ صرف کفار کے تجارتی قافلہ سے ان کا مقابلہ ہوگا.اسی وجہ سے بہت سے جاں نثار صحابہ ؓ اس جنگ میں شامل نہیں ہوسکے مگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ماتحت کفار اور مسلمانوں کے لشکر کو آمنے سامنے لے آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بتادیا کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ کفار سے جنگ کی جائے جب دونوں لشکر صف بستہ ہوگئے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓ نے اپنے دائیں بائیں دیکھا.وہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑی مدت سے یہ ولولے تھے کہ کبھی کفار سے جنگ ہو تو ان مظالم کا بدلہ لوں جو وہ مسلمانوں پر کرتے چلے آئے ہیں مگر سپاہی تبھی اچھا لڑ سکتاہے جب اس کا دایاں اور بایاں پہلو مضبوط ہو جو اس کی پیٹھ کو دشمن کے حملہ سے محفوظ رکھے.حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھنے کے لئے اپنے اردگردنظر ڈالی کہ آج میرے دائیں بائیں کون کھڑے ہیں تو میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ میرے دائیں طرف بھی پندرہ برس کا ایک انصاری لڑکا کھڑا تھا اور میرے بائیں طرف بھی پندرہ برس کا ایک انصاری لڑکا کھڑا تھا.یہ دیکھ کر مجھے سخت حسرت پیدا ہوئی کہ آج میں اپنے دل کے حوصلے کس طرح نکالوں گا.کاش میرے دائیں بائیں کوئی مضبوط اور ماہر فن سپاہی ہوتے تاکہ میں بھی اپنی مہارت کے جوہر دکھاسکتا.ان پندرہ پندرہ برس کے بچوں نے کیا کرنا ہے.وہ کہتے ہیں ابھی یہ خیال میرے دل میں گذرا ہی تھا کہ دائیں طرف کے انصاری نوجوان نے میرے پہلو میں آہستہ سے کہنی ماری.میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو اس نے کہا چچا
Page 278
ذرا جھک کر اپنے کان میں میری بات سننا (عرب میں رواج تھا کہ بڑی عمر والوں کو چھوٹے بچے اور نوجوان چچا کہا کرتے تھے) میں نے اس کی طرف کان جھکایا تو اس نے کہا چچا وہ ابوجہل کون سا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کرتا تھا.میرا جی چاہتا ہے کہ آج اس سے بدلہ لوں.وہ کہتے ہیں اس سوال پر میرے دل میں سخت حیرت پیدا ہوئی کہ یہ چھوٹاسا بچہ مجھ سے کیا سوال کررہا ہے.مگر ابھی میں نے اس کوکوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بائیں طرف سے میرے پہلو میں کہنی لگی.میں اس کی طرف مڑا تو اس نے کہا چچا ذرا جھک کر اپنے کان میں میری بات تو سننا.میں جھکا تو اس نے کہا چچا ابوجہل کون ہے.میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیا کرتا ہے.میرا جی چاہتا ہے کہ آج اس سے بدلہ لوں.ان دونوں نے آہستگی سے یہ بات اس لئے کہی کہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا دوسرا ساتھی اس بات کو سن لے اور وہ بھی اس شرف میں حصہ دار بن جائے.حضرت عبدالرحمٰن بن عوفؓکہتے ہیں باوجود تجربہ کار اور ہوشیار جرنیل ہونے کے میرے دل کے کسی گوشہ میں بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں ابوجہل کو مارسکوں گا.اس لئے جب ان دو نوجوان لڑکوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی.میں نے اپنی انگلی اٹھائی اور کہا دیکھو وہ جو فوج کے اندر کھڑا ہے جس نے سر پر خود پہنا ہوا ہے جو سر سے پائوں تک زرہ میں ملبوس ہے اور جس کے سامنے دو بہادر سپاہی ننگی تلواریں لئے پہرہ دے رہے ہیں وہ ابوجہل ہے.ان دو سپاہیوں میں سے ایک ابوجہل کا اپنا بیٹا عکرمہ تھا اور دوسرا ایک اور بہادر سردار تھا.وہ کہتے ہیں ابھی میرا ہاتھ نیچے نہیں گرا تھا کہ جس طرح باز چڑیا پر جھپٹا مارتا ہے اسی طرح وہ دونوں بے تحاشا دوڑ پڑے اور ایسی تیزی کے ساتھ دشمن کے لشکر میں جاگھسے کہ کفار حیرت سے منہ دیکھتے رہ گئے.انہیں ہوش ہی نہ آیا کہ وہ ان لڑکوں کو روکیں یہاں تک کہ وہ بڑھتے ہوئے ابوجہل کے سر پر جا پہنچے.اس وقت ایک محافظ کو خیال آیا اور اس نے تلوار چلائی جس سے ایک لڑکے کا ہاتھ کٹ گیا مگر اس نے کوئی پروا نہ کی اور جھٹ اپنے لٹکے ہوئے بازو پر اس نے پائوں رکھا اور اسے کھینچ کر جسم سے الگ کردیا.پھر دونوں نے آگے بڑھ کر ابوجہل کو ایسا شدید زخمی کیا کہ وہ زمین پر گرگیا گو مرا کچھ دیر بعد.ابو جہل کے لئے اس دنیا میں جہنم کا نظارہ غرض جنگ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ مدینہ کے دو نوجوان لڑکوں نے جن کو مکہ والے حقارت سے ذلیل کیاکرتے تھے ابوجہل کو مارگرایا.مدینہ کے لوگ سبزی ترکاری بیچ کر گذارہ کیا کرتے تھے اور جس طرح ہمارے ملک میں بعض زمیندار اپنی بیوقوفی سے آرائیوں کو حقارت سے دیکھا کرتے ہیں اسی طرح مکہ والے مدینہ کے لوگوں کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ سبزی ترکاری بیچنے والے لڑائی کے فنون کو کیا جانیں.مگر اللہ تعالیٰ کا نشان دیکھو کہ انہی مدینہ والوں میں سے دو نوجوان لڑکوں نے
Page 279
ابوجہل کو مارڈالا.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں جب لڑائی ختم ہوگئی تومیں یہ دیکھنے کے لئے نکلا کہ ابوجہل کا کیا حال ہے.میں نے دیکھا کہ وہ زخموں کی شدت کی وجہ سے کراہ رہا ہے.میں نے اسے کہا سنائو کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے اپنی موت کا غم نہیں کیونکہ سپاہی جنگ میں مرا ہی کرتے ہیں.مجھے افسوس ہے تو یہ کہ مدینہ کے نوجوانوں نے مجھے مارا(مسلم کتاب الـجھاد و السیر باب استحقاق القاتل سلب القتیل ).پھر اس نے عبداللہ بن مسعودؓ سے کہا کہ مجھے زخموں کی وجہ سے سخت تکلیف ہے.تم صرف اتنا کرو کہ تلوار سے میری گردن کاٹ دو مگر دیکھنا ذرا لمبی کاٹنا.کیونکہ جرنیلوں کی گردن ہمیشہ لمبی کاٹی جاتی ہے.حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں میں نے اسے کہا تیری اس آخری حسرت کو بھی پورا نہیں کروں گا.چنانچہ میں نے ٹھوڑی کے قریب سے اس کی گردن کاٹی(سیرۃ الحلبیۃ الجزو الثانی غزوۃ الکبرٰی).اب دیکھو ابوجہل کے دل میں اس وقت کتنی جلن ہوگی.کجا یہ کہ ابوجہل اس امید پر میدان میں آیا تھا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالوں گا اور کجا یہ کہ پندرہ پندرہ برس کے دو نوجوان لڑکوں نے اسے مار ڈالا اور مارا بھی ایسی حالت میں کہ اس کے سامنے پہرہ کے لئے دو زبردست جرنیل کھڑے تھے.ایک ان میں سے اس کا اپنا لڑکا تھا اور ایک اور جرنیل تھا.پھر اس نے زرہ بھی پہنی ہوئی تھی.خَود بھی اس کے سر پر تھا.مگر کوئی تدبیر کام نہ آئی اور وہ ہزاروں حسرتیں لئے ہوئے اس جہاں سے گذرگیا.اس وقت اس کے دل میں جو آگ جل رہی ہوگی اور جس حسرت سے اس نے اپنی جان دی ہوگی اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے.اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے جس شخص کو صلح کی گفتگو کے لئے اپنا لیڈر بناکر بھیجا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا بڑے دھڑلے سے باتیں کررہا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر اپنی فوقیت جتا رہا تھا کہ عین اسی وقت زنجیروںکی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آنی شروع ہوئی.لوگوں نے دیکھا تو اسی سردار کا لڑکا گرتا پڑتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آرہا تھا.جب وہ قریب پہنچا تو اس نے کہا یارسول اللہ میں آپ پر ایمان لاچکا ہوں.میرے باپ نے میرے پائوں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے گھر میں قید کررکھا تاکہ میں بھاگ کر مدینہ نہ پہنچ جائوں.آج یہ ادھر صلح کی گفتگو کے لئے آیا تو مجھے موقع مل گیا اور میں گرتے پڑتے یہاں پہنچ گیا(بخاری کتاب الشروط باب الشـروط فی الـجھاد والمصالـحۃ ).اس وقت اپنے بیٹے کی گفتگو سن کر کفار کے سردار کی جو حالت ہوئی ہو گی وہ کیسی عبرت ناک ہو گی وہ کفار کی طرف سے صلح کی گفتگو کے لئے آیا ہوا تھا اور سینہ تان کر بڑے فخر سے باتیں کر رہا تھا کہ عین اسی مجلس میں اس کا بیٹاآتا ہے اور اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میںڈالتے ہوئے کہتا ہے یارسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں.غرض اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے سامان پیدا کئے
Page 280
کہ کفار کے دل ہر وقت جل کر خاکستر ہوتے رہتے تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس آگ کو بجھانے کا ہم کیا انتظام کریں کوئی بڑا خاندان ایسا نہیں تھا جس کے افراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ آچکے ہوں.حضرت زبیرؓ ایک بڑے خاندان میں سے تھے حضرت طلحہؓ ایک بڑے خاندان میں سے تھے.حضرت عمرؓ ایک بڑے خاندان میں سے تھے.حضرت عثمانؓایک بڑے خاندان میں سے تھے.حضرت عثمان بن مظعونؓ ایک بڑے خاندان میں سے تھے.اسی طرح حضرت عمرؓو بن العاص اور خالد ؓ بن ولید مکہ کے چوٹی کے خاندانوں میں سے تھے.عاص مخالف تھے مگر عمرو مسلمان ہو گئے.ولید مخالف تھے مگر خالد مسلمان ہو گئے.غرض ہزاروںلوگ ایسے تھے جو اسلام کے شدید دشمن تھے مگر ان کی اولادوں نے اپنے آپ کو محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور میدان جنگ میں اپنے باپوں اور رشتہ داروں کے خلاف تلواریںچلائیں.حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ مختلف امور پر باتیں شروع ہو گئیں.حضرت عبدالرحمٰن جو حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے بدر یا احد کی جنگ میں کفار کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوئے تھے انہوں نے کھا نا کھاتے ہوئے باتوں باتوں میں کہا.ابا جان اس جنگ میں جب فلاں جگہ سے آپ گذرے تھے تو اس وقت میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا اور میں اگر چاہتا تو حملہ کر کے آپ کو ہلاک کر سکتا تھا مگر میں نے کہا اپنے باپ کو کیا مارنا ہے.حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خدا نے تجھے ایمان نصیب کرنا تھا اس لئے تو بچ گیا ورنہ خدا کی قسم اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو ضرور مار ڈالتا(روض الانف جلد ۳ صفحہ ۸۹،۹۰).غرض کفار کے لئے یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ جس مذہب کو مٹانے کے لئے وہ کمر بستہ رہتے تھے اسی مذہب میں ان کے اپنے بیٹے اور بھا ئی اور رشتہ دار شامل ہونے لگ گئے ان واقعات کو دیکھ دیکھ کر ان کے دلوں میں کس قدر حسرت پیدا ہوتی ہوگی.کہ ہم میں سے کسی کی بیوی اسلام میں داخل ہے،کسی کا باپ اسلام میں داخل ہے،کسی کا بیٹا اسلام میں داخل ہے کسی کا کوئی اور دوست اور رشتہ دار اسلام میں داخل ہے گویا وہ تو اپنی جانیں اسلام کے مٹانے کے لئے صرف کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں میں سے ایک ایک کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ رہا تھا،حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ جس مذہب کو کچلنے کے لئے وہ کھڑے تھے اسی مذہب میں ان کے اپنے دوست اور عزیز ترین رشتہ دار شامل ہو گئے اور وہ اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اپنے باپوںاور اپنے بھائیوں کے خلاف تلواریں چلانے لگ گئے.غرض فرماتا ہے نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ.اللہ تعالیٰ کفار کے دلوں پر ایک شدید آگ بھڑ کائے گا.
Page 281
لوگ بظاہر دیکھتے تو کہتے عاص بن وائل کتنا بڑا آدمی ہے بڑے فخر سے اپنا تہ بند لٹکا ئے چلا جا رہا ہے یا ولید کتنا بڑا آدمی ہے یا فلاں کتنا بڑا آدمی ہے مگر ان بڑے آدمیوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے دلوں میں ہر وقت ایک آگ لگی ہوتی تھی کہ ہمارا بیٹا مسلمان ہو گیا.ہمارا بھائی مسلمان ہو گیا.ہمارا فلاں رشتہ دار مسلمان ہو گیا ہم اب کریں تو کیا کریں.اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌۙ۰۰۹ (پھر)وہ (آگ اور تیز کرنے کے لئے)ان پر (سب طرف سے) بند کر دی جائے گی.فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍؒ۰۰۱۰ درانحا لیکہ(وہ لوگ اس وقت) لمبے ستو نوں کے ساتھ بندھے ہوں گے.حلّ لُغات.مُؤْصَدَۃٌ: اَلْمُؤْصَدُ اَلْمُطْبَقُ وَالْمُغْلَقُ.بند کی گئی (اقرب).عَـمَدٌ.عَـمُوْدٌ کی جمع ہے اور عَـمُوْدٌ کے معنے ستون کے ہیں(اقرب).تفسیر.اس آیت میں اس آگ کی شدت بیان کی گئی ہے جو کفار کے قلوب پر بھڑ کائی جانے والی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس آگ کو معمولی مت سمجھو.جس طرح بھٹی کی آگ سب آگوں سے زیا دہ شدید ہوتی ہے کیونکہ اسے ہر طرف سے بند کیا ہوا ہوتا ہے اسی طرح کفار کے قلوب پرجو آگ بھڑکائی جانے والی ہے وہ بھی نہایت شدید ہوگی.اسے چاروں طرف سے بند کرکے رکھا جائے گا اور اس کی بھڑاس بھی باہر نہیں نکلے گی.آگ کے کفار پر بند کئے جانے سے مراد اس’’بند آگ‘‘ کی مثال کفار مکہ کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے جنگ بدر کے بعد کیا.اس جنگ میں چونکہ مکہ والوں کے تمام چوٹی کے لیڈر ہلاک ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے سمجھا کہ اگر آج ماتم کیا گیا تو ہماری تمام عزت خاک میں مل جائے گی.چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ کوئی شخص بدر میں ہلاک ہونے والوں پر روئے نہیں.یہ حکم اپنی نوعیت کے لحاظ سے نہایت شدید تھا مگر اپنی قوم کے فیصلہ کا احترام کرتے ہوئے مکہ کا ایک ایک فرد اپنے سینہ میںغم و الم کی ایک بے پناہ آگ دبا کر خاموش ہو گیا.ان کی آنکھیں اپنے مرنے والوں کی یاد میںآنسو ئوں کی موسلا دھار بارش برسانا چاہتی تھیں ان کی زبانیں آہ و فغاں اور
Page 282
نالہ و فریاد سے ایک شور بر پا کرنا چاہتی تھیں مگر وہ کیا کر سکتے تھے قوم کا فیصلہ تھا کہ آج تمہارے لئے ماتم جائز نہیں.تم اپنی زبانوں کو بند رکھو.تم اپنے آنسوئوں کو مت گرنے دو ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں تک یہ خبریں پہنچیںتو وہ خوش ہوں کہ ہم نے خوب بدلہ لیا.یہ حالت ایک لمبے عرصہ تک رہی.عورتوں کو اپنے خاوندوں پر، مائوں کو اپنے بیٹوں پر، بھائیوں کو اپنے بھائیوں پر، اور دوستوں کو اپنے دوستوں پر رونے کی اجازت نہیں تھی.ان کے سینے اس بند آگ کی تپش سے اندر ہی اندر جل رہے تھے مگر قوم کے فیصلہ کی خلاف ورزی کی ان میں سے کسی میں جرأت نہیں تھی.ایک دن کسی مسافر کی اونٹنی مر گئی اور اس نے مکہ کی گلیوں میںسے گذرتے ہوئے اس کے غم میں ماتم کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا.یہ آواز سن کر ایک بوڑھا شخص جس کے دو نوجوان بیٹے اس جنگ میں ہلاک ہو چکے تھے کود کر اپنے گھر میں سے باہر نکل آیا اور اس نے بلند آواز سے کہا ہائے افسوس اس شخص کو اپنی اونٹنی پر رونے کی اجازت ہے مگر مجھے جس کے دو نوجوان بیٹے جنگ میں مارے گئے ہیںرونے کی اجازت نہیں دی جاتی.اس کا یہ کہنا تھا کہ یک دم تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں سے نکل آئے اور انہوں نے کہا ہم تو جل کر مر گئے ہیں.ہم آگ سے پھنکے جا رہے ہیں ہم اب زیادہ صبر نہیں کر سکتے.چنانچہ انہوں نے چوکوں اور بازاروںمیں جمع ہو کر پیٹنا شروع کر دیا اور تمام مکہ میں ایک کہرام مچ گیا(سیرۃ ابن ھشام غزوہ بدر زیر عنوان ذکر رؤیا عاتکۃ بنت عبد المطلب ).غرض فرماتا ہے نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِيْ.تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ آگ ان کے دلوں پر خوب بھڑکائی جائے گی اور پھر وہ آگ چاروں طرف سے بند ہو گی.اس کے شعلے ان کی ایڑی سے لے کر چوٹی تک پہنچیں گے اور انہیں جھلس کر رکھ دیں گے.فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ.یہ عَلَيْهِمْ کی ضمیر مجرور کا حال واقعہ ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ مُوْثَقِیْنَ فِیْ عَـمَدٍ مُّـمَدَّدَۃٍ کفار کا یہ حال ہو گا کہ جب آگ ان پر بھڑکائی جائے گی تو وہ بڑے بڑے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوں گے.جس طرح ستون سے اگر کسی شخص کو باندھ دیا جائے تو اس کا جسم اکڑا رہتا ہے اور باوجود کوشش کے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اسی طرح فرماتا ہے ہم ان کفار کو ایسا عذاب دیں گے کہ وہ باوجود کوشش اور خواہش کے اس عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں پائیں گے چنانچہ یہ پیشگوئی اس رنگ میں پوری ہوئی کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اپنے بیٹے، بھائی، دوست اور رشتہ دار سب مسلمان ہو گئے.کوئی اور قوم ابتدا میں مسلمان ہوتی تو شاید ان کو اتنی تکلیف نہ ہوتی مگر جب ان کے اپنے جگر گوشے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تو یہ ان کے لئے ایسی ہی بات تھی جیسے کسی کو اونچے ستون سے باندھ دیا
Page 283
جائے اور وہ حرکت تک نہ کر سکے.اونچے ستونوں کے الفاظ اس لئے استعمال کئے گئے کہ عام طور پر سنگساری اور جلانے کے لئے کمر تک گڑی ہوئی لکڑی یا ستون سے باندھا کرتے تھے.بڑے ستون کہہ کر بتایا کہ جسم کا اوپر کا حصہ بھی جکڑا ہو اہو گا.فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ کے دو معنے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ کو مُؤْصَدَۃٌ کی صفت قرار دیا جائے.مُـمَدَّدَۃٌ کے معنی چونکہ مُطَوَّلَۃٌ کے ہیںاس لئے اس آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ بڑے بڑے لمبے ستونوں میںآگ جل رہی ہو گی یعنی جس بھٹی میں وہ جلائے جائیں گے وہ بہت بلند ہو گی اور لمبے ستونوں سے بنی ہوئی ہوگی.یہ قاعدہ ہے کہ جتنی لمبی بھٹی ہوتی ہے اتنی آگ زیادہ تیز ہوتی ہے پس فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ میں ایک طرف تو اس آگ کی شدت بیان کی گئی ہے کہ وہ انتہا درجہ کی حدّت اپنے اندر رکھتی ہو گی اور دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کی حالت ایسی ہو گی جیسے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں.وہ بچنے کی بہت کوشش کریں گے مگر انہیں اپنے بچائو کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی.چنانچہ آخر یہی حالت کفار مکہ کی ہو گئی جب ان کے اپنے بیٹے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کی بات کون سنتا تھا.اگر وہ ان سے کہتے بھی کہ تم ہم میں پھر واپس آجائو اور اپنا آبائی مذہب اختیارکر لو تو ان کی بات ماننے کے لئے کون تیار ہو سکتا تھا.یہ ایمان کا معاملہ تھا اس میں کسی باپ یا ماں کا کیا دخل تھا اور کون شخص ان کی بات مان سکتا تھا.غرض فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ کے دونوں معنے ہو سکتے ہیں.یہ بھی کہ ان کے لئے عذاب کی بھٹیاں بڑی بڑی اونچی بنائی جائیں گی اور یہ بھی کہ وہ با لکل بے کس اور بے بس ہو جائیں گے.انہیں عذاب پہنچے گا مگر وہ سر سے پا تک بندھے ہوئے ہوں گے کچھ کر نہیں سکیں گے.
Page 284
سُوْرَۃُ الْفِیْلِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ الفیل.یہ سورۃ مکی ہے وَہِیَ خَـمْسُ اٰیَاتٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَ فِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے سوا پانچ آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ الفیل مکی سورۃ ہے سورۃ الفیل مکہ میں نازل ہوئی ہے.حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورۃ مکی ہے(فتح البیان زیرسورۃ الفیل) اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سورۃ کے مکی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں.مغربی مستشرقین کے نزدیک بھی یہ سورۃ مکی ہے.جرمنی کا مشہور مستشرق نولڈکے اسے نہایت ابتدائی سورتوں میں سے قرار دیتا ہے اور سورۂ تکاثر کے زمانہ کی بتاتا ہے.(A Comprehensive on The Quran by Wherry, vol:4 ) سورۃ الفیل کا تعلق سورۃ الھمزۃ سے اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے ایک تو اس لمبے تعلق کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے ہے جس کا ذکر میں اس سے پہلے کی شائع شدہ تفسیر میں کر چکا ہوں.یعنی قرآن کریم کی یہ آخری سورتیں سوائے چند آخری سورتوں کے باری باری اسلام کے ابتدائی زمانہ کے متعلق اور اسلام کے آخری زمانہ کے متعلق آتی ہیں.ایک سورۃ میں اسلام کے ابتدائی زمانہ کا خصوصیت سے ذکر ہوتاہے اور دوسری سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے.میری یہ مراد نہیں کہ جس سورۃ میں اسلام کے ابتدائی زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں آخری زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا اور نہ یہ کہ جس سورۃ میں اسلام کے آخری زمانہ کا ذکر آتا ہے اس میں ابتدائی زمانہ کا ذکر نہیں ہوتا.بالعموم دونوں ہی ذکر ہوتے ہیں.لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک سورۃ میں مدّ ِنظر اسلام کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے اور دوسری سورۃ میں خصوصیت کے ساتھ مدّ ِنظر اسلام کا آخری زمانہ ہوتا ہے.پس یہ سورتیں خصوصیت کے لحاظ سے ابتدائی یا آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں.یہ نہیں کہ پہلے اور دوسرے زمانہ کا اکٹھا ذکر نہیں ہوتا.بسا اوقات بڑے زور سے ہوتا ہے.مگر وہ مقصود اوّل نہیں ہوتا.مقصود اوّل صرف ایک ذکر ہوتا ہے اور یہ دور باری باری چلتا ہے.اس لحاظ سے سورۃ الفیل آخری زمانہ کے متعلق معلوم ہوتی ہے یعنی اس میں خصوصیت کے ساتھ آخری زمانہ
Page 285
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے.گو ذکر اس میں پہلے زمانہ کا ہے مگر مقصود آخری زمانہ کی طرف اشارہ کرنا ہے.قریبی ترتیب کے لحاظ سے اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ.عیب چینیاں کرنے والے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے اور تکلیفیں دینے والے لوگ جو اپنے مال اور دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں وہ تباہ اور برباد کئے جائیں گے.یہ حکم تو عام تھا کیونکہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ.ہر ایسے شخص پر عذاب آئے گا جو ہُـمَزَۃ اور لُمَزَۃ ہو گا لیکن مقصود اوّل اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دشمن مالدار تھے، دولتمند تھے، ان کی بڑی بڑی تجارتیں تھیں، بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، تمام ملکی اقتدار ان کے قبضہ میں تھا اور وہ اپنے مال و دولت اور رتبہ کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ان طاقتوں اور قوتوں کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کسی صورت میں بھی ان پر غالب نہیں آسکتے.اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے تمہارا یہ خیال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر غالب نہیں آسکتے قطعی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئیں گے اور تم لوگ جو بڑے کہلاتے ہو اور مال و دولت کے غلط استعمال کی وجہ سے غریبوں کو ستاتے اور دکھ دیتے ہو ناکام و نامراد رہو گے.غرض اس سورۃ میں یہ خبر دی گئی تھی کہ یہ لوگ بڑے دکھ میں مبتلا ہوں گے.ان کی تباہی کامل ہو گی اور ان کا انجام نہایت دردناک ہو گا.یہاں قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کس طرح ہو گا.عقل میں تو یہ نہیں آسکتا کہ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے عقلمند، بڑے بڑے مدبر اور بڑی بڑی طاقتوں والے ہار جائیں اور کمزور جیت جائے.جن کے پاس حکومت ہو وہ تو شکست کھا جائیں اور جو ہمسائیوں کے مظالم کا شکار ہو رہا ہو وہ فتح حاصل کر لے.پس چونکہ یہ اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ عقل اس بات کو نہیں مان سکتی.اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں ایک ایسا واقعہ پیش کیا ہے جسے کوئی عقل نہیں مان سکتی تھی.اس میں جو کچھ ہوا الٰہی تقدیر کے ماتحت ہوا اور عقل کے بالکل خلاف نتیجہ پیدا ہوا اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس دنیا میں صرف وہی کچھ نہیں ہوتا جو عقل کے مطابق ہو بلکہ ایسے واقعات بھی رونما ہو جایا کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہوتے ہیں جیسا کہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے.ایک بادشاہ نے جس کی بہت بڑی اور منظم حکومت تھی مکہ پر حملہ کیا.مگر جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی باوجود ساری طاقتوں اور قوتوں کے وہ ہار گیا اور مکہ کے لوگ جو بے سر و سامان تھے جیت گئے.یوں تو ہُـمَزَۃ اور لُمَزَۃ ہرجگہ ہوتے ہیں مگر اس جگہ پہلے مخاطب مکہ کے ہُـمَزَۃ اور لُمَزَۃ ہی تھے اور انہیں کے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ الَّذِيْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ.يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم مال و دولت کے زور سے غالب آجائیں
Page 286
گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلہ میں ہار جائیں گے.اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں کو فرماتا ہے کہ تمہارے مکہ میں ایک مثال موجود ہے تم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے آپ کو بڑا کہہ رہے ہو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم سے بھی بڑے بڑے لوگ دنیا میں موجود تھے.تم سے بھی بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں موجود تھیں.تم سے بھی بڑی بڑی طاقتیں دنیا میں موجود تھیں.چنانچہ انہیں حکومتوں اور طاقتوں سے ایک نے مکہ پر حملہ کیا اور تم لوگوں نے بغیر مقابلہ کئے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے.لیکن مکہ چونکہ خدا کے ایک پیارے کا صدر مقام بننے والا تھا اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ کی ایک پیاری جگہ اور اس کا مقدس مقام تھا.اللہ تعالیٰ نے دشمن کے ارادوں کو باطل کر دیا اور اس کی تدبیروں کو توڑ کر رکھ دیا.چنانچہ آخر مکہ ہی غالب رہا اور وہ بڑا طاقتور دشمن ناکام و نامراد رہا.یہ مثال تمہارے سامنے موجود ہے عقل میں وہ بات بھی نہیں آتی تھی مگر آخر ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ کا منشا تھا.کیا اس مثال کو دیکھتے ہوئے اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی جتھہ نہیں، کوئی طاقت نہیں وہ کس طرح جیت جائیں گے اور مکہ والے جو طاقتور اور جتھہ والے ہیں ان کے مقابلہ میں کس طرح ہار جائیں گے.تم اصحاب الفیل کے واقعہ کو مدّ ِنظر رکھو اور یہ سمجھ لو کہ جس طرح وہاں ہوا اسی طرح اللہ تعالیٰ اس موقع پر بھی اپنی قدرت کا زبردست نشان دکھائے گا.اور تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں مغلوب کر دے گا.سورۃ الفیل کا سورۃ ہمزہ سے دوسرا تعلق دوسرا تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ اس میں دلیل بالاولیٰ کے طور پر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ خانۂ کعبہ مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ خانۂ کعبہ ایک علامت تھی آنے والے کی.ایک عظیم الشان انسان نے دعائے ابراہیمی کے ماتحت دنیا کی ہدایت کے لئے آنا تھا اور اس کے لئے ایک مرکز کی ضرورت تھی.اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو مقدس قرار دیا اور اسے لوگوں کا مرجع بنا دیا مگر بہرحال یہ مقصود نہیں تھا.مقصود وہی تھا جس نے دعائے ابراہیمی کے ماتحت ظاہر ہونا تھا اور جس کا کام یہ بتایا گیا تھا کہ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ.وہ خدا کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سنائے گا.ان کے دلوں کو پاک کرے گا.انہیں احکام الٰہیہ کی حکمتیں سکھائے گا.انہیں خدا تعالیٰ کی شریعت کے اسرار سمجھائے گا.اور ان میں پاکیزگی اور طہارت پیدا کرے گا یہ انسان اصل مقصود تھا مکان اصل مقصود نہیں تھا.مکان تو صرف ایک علامت تھی اصل اہمیت رکھنے والی وہ چیز تھی جو اس کے پیچھے تھی اور درحقیقت اگر ہم غور سے کام لیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ظاہری چیزیں اہمیت نہیں رکھتیں.بلکہ اصل اہمیت اسی چیز کی ہوتی ہے جو ان چیزوں کے پیچھے ہوتی ہے
Page 287
اور ان کا محرک ہوتی ہے.لطیفہ مشہور ہے کہ شیخ سعدی ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے کسی سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک دن شہر کے رئیس نے دعوت کی اور اس نے اعلان کرا دیا کہ وہ مسافر جو سراؤں میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی میرے ہاں مدعو ہیں.سرائے والے نے شیخ سعدی کو بتا دیا کہ آج آپ کو یہاں سے کھانا نہیں ملے گا.کیونکہ فلاں رئیس نے دعوت کی ہے اور آپ کو بھی اس نے بلایا ہے.شیخ سعدی گو آدمی بہت بڑے تھے مگر لباس نہایت سادہ رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو بادشاہوں کے دربار میں جانے کی عادت تھی اور چونکہ وہ بہت مشہور تھے جس جگہ بھی جاتے لوگ ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کے مقام پر بٹھاتے.اسی عادت کے مطابق وہ اس رئیس کے ہاں گئے اور سیدھے صدر کی جگہ کے قریب بیٹھ گئے.انہیں یہ خیال ہی نہ رہا کہ یہ نئی جگہ ہے اور یہاں لوگ مجھے نہیں جانتے.اتنے میں کوئی بہت بڑا رئیس آگیا.صاحب خانہ کے ملازم شیخ سعدی کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ حضور جگہ چھوڑیئے فلاں صاحب تشریف لائے ہیں.شیخ سعدی وہاں سے اٹھے اور دوسری جگہ بیٹھ گئے.تھوڑی دیر گذری تھی کہ ایک اور رئیس آگئے.پھر ملازموں نے شیخ سعدی کو وہاں سے اٹھایا اور وہ ہٹ کر پَرے بیٹھ گئے.وہاں بیٹھے تھے کہ ایک اور رئیس آگیا اور انہیں وہاں سے بھی اٹھنا پڑا.اسی طرح ہوتے ہوتے وہ جوتیوں کی جگہ پر پہنچ گئے.خیر انہوں نے کھانا کھا لیا اور چلے گئے.چونکہ اس رئیس کی طرف سے تین دن کی دعوت کا اعلان تھا.شیخ سعدی چونکہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے اور ان کی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے اس لئے مختلف بادشاہوں کی طرف سے انہیں بڑے بڑے قیمتی خلعت ملے ہوئے تھے.دوسرے دن دعوت پر جاتے ہوئے انہوں نے کسی بڑے بادشاہ کا دیا ہوا ایک نہایت قیمتی خلعت نکالا اور پہن لیا.اس میں موتی اور جواہرات ٹنکے ہوئے تھے.اور سونے کے کام سے بھرا ہوا تھا جب دعوت کی جگہ پر پہنچے تو بجائے مسند پر بیٹھنے کے جاتے ہی دروازے کے پاس جاکر بیٹھ گئے.اتنے میں اسی رئیس کا ایک نوکر آیا اور اس نے کہا حضور آپ یہاں کیوں تشریف رکھتے ہیں اٹھیے اور اوپر چلیے.وہ اٹھ کر اس سے اوپر کی جگہ بیٹھے.ایک اور ملازم آگیا اور اس نے کہا.حضور یہاں کہاں بیٹھے ہیں اوپر ہوکر بیٹھئے.یہ کچھ اوپر ہو کر بیٹھ گئے.وہاں بیٹھے تھے کہ ایک اور نوکر نے دیکھ کر کہا حضور یہ جگہ آپ کے لئے مناسب نہیں آپ مسند کے قریب تشریف لائیے.آخر صاحب خانہ تشریف لائے اور انہوں نے شیخ سعدی کا جو لباس دیکھا تو سمجھا کہ کوئی وزیر یا بڑا امیر کسی مملکت کا آیا ہے اور ان سے آکر کہا کہ آپ مجھے کانٹوں میں کیوں گھسیٹتے ہیں آئیے اور مسند پر بیٹھئے چنانچہ اس نے شیخ سعدی کا اس قدر احترام کیا کہ خود بھی مسند پر نہ بیٹھا اور انہیں جگہ دے دی جب کھانا
Page 288
سامنے آیا تو شیخ سعدی نے خلعت لپیٹ کر شوربے میں ڈبو دیا.لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی پاگل ہے جو ایسی حرکت کررہا ہے.صاحبِ خانہ نے بھی کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں.انہوں نے کہا جناب یہ میری دعوت نہیں اسی خلعت کی دعوت ہے اس لئے میں اسے کھلا رہا ہوں.انہوں نے کہا ہم تو سمجھے نہیں آپ کا مطلب کیا ہے وہ کہنے لگے میں ہی کل اس دعوت میں آیا تھا مگر مجھے دھکے دیتے دیتے جوتیوں تک پہنچا دیا گیا.مگر آج میں جوتیوں میں بیٹھا تو مجھے آگے لاتے لاتے مسند تک پہنچا دیا گیا.آخر میں تو وہی ہوں جو کل بھی اس مجلس میں آیا تھا.پھر مجھ سے جو سلوک میں فرق کیا گیا ہے وہ کیوں ہے.اسی لئے کہ آج میں نے خلعت پہنا ہوا ہے.مگر کل میں نے خلعت نہیں پہنا تھا.پس درحقیقت یہ اسی لباس کی دعوت ہے میری دعوت نہیں.شیخ سعدی مستغنی آدمی تھے انہیں خلعت کے خراب ہونے یا رہنے کی پروا ہی کیا تھی.جب صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو اس نے معذرت کی اور کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی ہمیں معاف کیا جائے.یہ بظاہر ایک لطیفہ ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ سعدی کے مقابلہ میں خلعت کی کیا حقیقت تھی.نادان سمجھتے ہوں گے کہ شاید خلعت کی وجہ سے سعدی کی عزت تھی مگر جو عقلمند تھے وہ جانتے تھے کہ اس خلعت کی عظمت اس میں ہے کہ سعدی نے اس کو پہنا ہے نہ یہ کہ سعدی کو اس خلعت کی وجہ سے عزت حاصل ہے.اسی طرح خانۂ کعبہ کی اپنی ذات میں کوئی عزت نہیں تھی خانۂ کعبہ کو اگر عزت حاصل تھی تو اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادی اٹھائیں تا موعود کل ادیان ظاہر ہو کر اس سے تعلق پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لئے ایک مقامِ اتحاد اور اقوامِ عالم کے لئے مرجع بنا دیا.اسی نقطۂ نگاہ کے ماتحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ تو دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس کے ظہور کے لئے خانۂ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھیں.تم کہتے ہو کہ یہ غریب ہے کمزور ہے، ناطاقت ہے اور ہم بڑے دولتمند ہیں یہ ہمارے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا.تمہیں سمجھنا چاہیے کہ خانۂ کعبہ کی قیمت زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت زیادہ ہے.خانۂ کعبہ کی تو بنیاد ہی اسی لئے رکھی گئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں.چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو دعا کی اس میں کھلے طور پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ(البقرہ:۱۳۰) پس خانہ کعبہ قائم ہی اسی لئے کیا گیا تھا کہ تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرنے والا نبی اس جگہ پیدا ہو.اگر علامت کے لئے خدا نے یہ نشان دکھایا تھا کہ اس نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تو تم سمجھ لو کہ اس مقصود کے لئے وہ کتنا بڑا نشان ظاہر کرے گا.جب ایک علامت کے لئے اس نے اصحاب الفیل کو تباہ کر دیا تو
Page 289
وہ چیز جو مقصود بالذات ہے اس کے لئے تو وہ جتنی بھی غیرت دکھائے کم ہے.حالانکہ اصحاب الفیل کو جو طاقت حاصل تھی وہ مکہ والوں کو نہیں تھی.گویا مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تم تو اصحاب الفیل کے مقابلہ میں بھی ذلیل تھے.جب تمہارے جیسے ذلیل انسانوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے حملہ سے مکہ کو بچایا تو کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ تمہارے حملہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بچائے گا.سورۃ الفیل کا سورۃ ہمزہ سے تیسرا تعلق تیسرا قریبی تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ مکہ کا بچانا بھی گو اصحاب الفیل کی تباہی کی ایک وجہ تھی.مگر اصل وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی اور یہ مقصد اور تمام مقاصد سے زیادہ مقدم اور اہم تھا.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خانۂ کعبہ کو بچانا خود بھی ایک مقصود تھا مگر بعض دفعہ ایک سے زیادہ بھی مقصود ہو جاتے ہیں.مثلاً بعض دفعہ حکومت باہر سے آنے والے وزراء کی دعوت کرتی ہے تو وہ وزیر اعظم کی بھی دعوت کرتی ہے، وزیر خارجہ کی بھی دعوت کرتی ہے، وزیر تعلیم کی بھی دعوت کرتی ہے، وزیر مال کی بھی دعوت کرتی ہے.اسی طرح دوسرے وزراء کی بھی دعوت کرتی ہے مگر مقدم وزیر اعظم کی دعوت ہوتی ہے.وزیر خارجہ یا وزیر مال یا وزیر تعلیم کی دعوت مقدم نہیں ہوتی.اسی طرح مکہ کے بچانے میں جہاں تک خانۂ کعبہ کی حفاظت مدّ ِنظر تھی وہاں اس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام مدّ ِنظر تھا جو تھوڑے ہی دنوں تک پیدا ہونے والے تھے اور جس کی تفصیل آگے آئے گی.اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جیت جائیں گے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر اصحاب الفیل کو تباہ کر دیا.اب کیا تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تو اس نے آپؐکے لئے ایسا عظیم الشان نشان دکھا دیا تھا.مگر پیدا ہونے کے بعد وہ آپ کو چھوڑ دے گا جس انسان کی حیثیت اتنی عظیم الشان تھی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے اپنے نشانات کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا تم سمجھ سکتے ہو کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کا کتنا بڑا احترام ملحوظ ہو گا اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے وہ کیا کچھ نہ کرے گا.پس تمہیں اپنا فکر کر لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم اس کی مخالفت میں اپنی عاقبت تباہ کر لو.سورۃ الفیل کا سورۃ ہمزہ سے چوتھا تعلق چوتھا قریبی تعلق اس سورۃ اور پہلی سورۃ کا یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں دشمن کے مال و دولت کے مالک ہونے کا دعویٰ بیان کیا گیا تھا.دشمن کا دعویٰ تھا کہ میں بڑا مالدار ہوں اور اس کی وجہ سے میں ہمیشہ ہمیش قائم رہوں گا.اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے واقعہ کو پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ اصحاب الفیل بھی بڑے دولتمند تھے اور ان کی دولت سے تمہاری دولت زیادہ نہیں مگر باوجود اس کے کہ وہ
Page 290
بڑے دولتمند تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا.پس تمہارا یہ خیال کر لینا کہ چونکہ ہمارے پاس بڑی دولت اور مال ہے اس لئے ہم تباہ نہیں ہو سکتے غلط ہے.خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں اگر تم کھڑے ہو گے تو ضرور کاٹے جاؤ گے.اس کی تلوار کے سامنے بڑا اور چھوٹا کوئی حیثیت نہیں رکھتا.سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں.وہ دشمن ایک ایسے گرجا کو بچانے کے لئے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا جس میں جابجا قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے.سنگِ مرمر کا اس میں کام کیا گیا تھا.دور دور سے انجینئر اس کی تعمیر کے لئے منگوائے گئے تھے.سونے کا پانی اس پر پھروایا گیا تھا اور نہایت قیمتی پتھر اس میں جڑوائے گئے تھے.اس کے مقابلہ میں ظاہری قیمت کے لحاظ سے خانۂ کعبہ کی کیا حیثیت ہے.اگر ظاہری قیمت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلہ میں اس کی کچھ بھی حیثیت نہیں.پس تم اگر دولت کا گھمنڈ کرتے ہو تو اس گرجا کے بنانے والوں کے پاس زیادہ دولت تھی مگر جب وہ بھی خدا تعالیٰ کے مقابلہ میں آئے تو تباہ ہو گئے.سورۃ الفیل کا سورۃ ہمزہ سے پانچواں تعلق پانچواں قریبی تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ اگلے جہان کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی سورۃ میں فرمایا گیا تھا کہ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ.وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ.نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ.الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ.اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ.فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (الھمزۃ:۵تا۱۰) میں بتا چکا ہوں کہ ان آیات میں خصوصیت سے اس دنیا کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے.مگر اس کے ظاہری معنے چونکہ یہی نظر آتے ہیں کہ اگلے جہان میں کفار پر اس رنگ میں عذاب نازل ہو گا.اس قسم کی آیات پر کفار شور مچا دیا کرتے ہیں کہ اگلا جہان تو کسی نے دیکھا نہیں.پس تم اگلے جہان کے عذابوں کا ذکر کر کے درحقیقت لوگوں کو دھوکا دیتے ہو اور ایک ایسی بات پیش کرتے ہو جس کی تصدیق اس دنیا میں نہیںہو سکتی.جیسے اب تک بھی یوروپین مصنف یہی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اگلے جہان کے عذابوں سے ڈرا ڈرا کر لوگوں کو مسلمان کر لیا (The Encyclopedia of Religion And Etheics, Under Word Ethics and Morality).یہی عرب لوگ کہتے تھے کہ قرآن کریم ایسے عذابوں کی خبر دیتا ہے جو اس جہاںسے تعلق نہیں رکھتے وہ صرف ایسے عذابوں کا ذکر کرتا ہے جو اگلے جہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور اگلا جہان ہم نہیں مانتے پھر ہم ان باتوں کو کس طرح درست تسلیم کر لیں.اس کے جواب کے لئے قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ جہاں وہ کسی اخروی عذاب یا انعام کا ذکر کرتا ہے وہاں کسی نہ کسی دنیوی عذاب یا انعام کا ضرور ذکر کرتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ تم اخروی عذاب یا انعام یا نتیجہ کے متعلق تو کہہ سکتے ہو کہ ہم ان باتوں کو کس طرح مان لیں یہ تو اگلے جہان سے تعلق رکھتی ہیں.مگر تم دنیوی امور کے متعلق یہ بات نہیں کہہ سکتے اس لئے ہم اخروی عذابوں یا انعاموں
Page 291
کے ذکر کے ساتھ ہی بعض دنیوی امور سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو موجودہ حالات میں بالکل ناممکن نظر آتی ہیں.اگر یہ ناممکن نظر آنے والی باتیں ممکن ہو جائیں اور تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ باتیں پوری ہو جائیں تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس خدا نے ان غیر ممکنات کو ممکنات کی صورت دے دی ہے وہ اخروی عذابوں کو بھی اسی رنگ میں پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے.اسی وجہ سے قرآن کریم کا یہ ایک عام قانون ہے کہ وہ اخروی اور دنیوی عذابوں اور انعاموں کو آپس میں ملا کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ دنیوی عذاب اور انعام اخروی عذابوں اور انعاموں کی صداقت پر گواہ ہوں اور کفار ان کے انکار کی جرأت نہ کر سکیں.غرض اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل کو کفار کے اس اعتراض کے جواب میں بیان کیا ہے کہ اگلے جہان کے عذابوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.تمہیں یہ بات عقل کے خلاف اور ناممکن نظر آتی ہے مگر ایسی ہی ناممکن بات اصحاب الفیل کی بربادی کی بھی تھی.ان کا حملہ ایسے رنگ میں ہوا اور ایسے حالات میں ہوا اور عربوں کا دفاع اتنا کمزور پڑ گیا اور انہوں نےا پنے آپ کو ابرہہ اور اس کے لشکر کے مقابلہ میں اتنا بےکس اور بے بس پایا کہ ہتھیار ڈال دیئے اور سمجھ لیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے.مگر باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے سامانوں اور ذرائع سے دشمن کو تباہ کیا گیا کہ جس کی مثال دنیا میں ڈھونڈے سے بھی نہیں مل سکتی.فرماتا ہے تم غور کرو اور سوچو کہ وہاں کیا بات تھی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو تباہ کیا.اس کا لشکر اس لئے تباہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شہر کو امن والا بنائے گا.اور اسے دشمنوں کے حملہ سے محفوظ رکھے گا.ابراہیمؑ کے وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ جناب آپ نے یہ دعویٰ تو کر دیا ہے مگر اس کا ثبوت کیا ہے.یہ تو آئندہ زمانہ کے متعلق آپ ایک بات کہہ رہے ہیں.اور اس زمانہ میں نہ ہم زندہ ہوں گے نہ آپ نے زندہ رہنا ہے.پھر ایسی بات کا فائدہ کیا ہے مگر جب وہ وقت آیا دیکھنے والوں نےد یکھ لیا کہ ابراہیمؑ کی پیشگوئی پوری ہوئی اور ایک زبردست دشمن جو لشکر جرار کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچا لیااور اس طرح ایک ناممکن بات ممکن ہو گئی.حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسمٰعیلؑ کو وادیٔ غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیشگوئی کی تھی اس وقت مکہ دنیا میں کوئی شہر نہیں تھا.محض اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے لئے انہوں نے اپنی بیوی اور ایک چھوٹے بچے کو جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا اس مقام پر آکر چھوڑ دیا.اس وقت تک ابھی زمزم کا چشمہ بھی نہیں پھوٹا تھا.بالکل وادیٔ غیر ذی زرع کی سی حالت تھی نہ اس میں پانی کا
Page 292
کوئی سامان تھا نہ کھانے کا کوئی سامان تھا صرف ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی خشک کھجوروں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس رکھ دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت وہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر واپس چل پڑے.انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا نہیں کہ میں تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ انہیں خیال گذرا کہ ماں کی مامتا اپنے بچہ کی تکلیف کی وجہ سے شاید اس کی برداشت نہ کر سکے.جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے تو آپ نے اس محبت کی وجہ سے جو طبعاً انسان کو اپنی بیوی اور بچے سے ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انہیں مڑ کر دیکھنا شروع کر دیا.پہلے تو وہ اس رنگ میں باتیں کرتے رہے کہ بیوی کو یہ شبہ پیدا نہ ہوا کہ میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جب وہاں سے واپس چلے تو واپس لوٹتے وقت بھی اس انداز میں واپس گئے جیسے کوئی ایندھن اکٹھا کرنے جاتا ہے یا پانی کا انتظام کرنے کے لئے جاتا ہے مگر جب چل پڑے تو ان سے برداشت نہ ہو سکا اور تھوڑے فاصلہ پر جا کر انہوںنے اپنی بیوی اور بچے کی طرف دیکھا اور پھر چلے اور چند قدم اٹھائے تو محبت نے غلبہ پایا اور انہوں نے دوبارہ اپنی بیوی اور بچے کی طرف دیکھاپھر چلے تو تھوڑی دیر کے بعد محبت نے پھر جوش مارا اور پھر انہوں نے اپنی بیوی اور بچے پر نظر ڈالی.حضرت ہاجرہؓ اپنے خاوند کی ان حرکات سے سمجھ گئیں کہ یہ جدائی عارضی نہیں بلکہ معلوم ہوتا ہے یہ مستقل طور پر جا رہے ہیں کیونکہ ان کے چہرے پر رقت کے آثار تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے.حضرت ہاجرہؓ نے سمجھ لیا کہ بات کچھ اور ہے.وہ گھبرا کر اٹھیںاور حضرت ابراہیمؑ کے پاس گئیں اور کہا کہ کیا آپ ہم کو چھوڑے چلے جار ہے ہیں.حضرت ابراہیمؑ رِقّت کی وجہ سے کوئی جواب نہ دے سکے.ان کا گلا پکڑا گیا.ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا.حضرت ہاجرہؓ کو یقین آ گیا کہ اب یہ ہم کو مستقل طور پر چھوڑے چلے جارہے ہیں.چونکہ حضرت ہاجرہؓ کا پہلے بھی اپنی سَوت کے ساتھ جھگڑا ہو چکا تھا اس لئے انہیں خیال آیا کہ شاید یہ اس کی وجہ سے نہ ہو.پھر خیال آیا کہ چونکہ حضرت ابراہیمؑ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے شاید اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اس بات کا حکم نہ دیا ہو چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ءَ اَللہُ اَمَرَکَ.کیا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ایسا کرو.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثبات میں سر ہلا دیا.مگر غم کی وجہ سے ان سے بات نہیں کی گئی.حضرت ہاجرہؓ نے یہ سن کر کہا اگر خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے تو خدا ہم کو چھوڑے گا نہیں.آپ بےشک چلے جائیں(تفسیر جامع البیان زیر آیت رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ....).جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑا ہے اس وقت مکہ کوئی شہر نہیں تھا.وہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی وہاں پینے کی کوئی چیز نہیں تھی.صرف ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلی کھجوروں کی وہ انہیں دے کر
Page 293
واپس چلے گئے اور اس لئے گئے کہ خدا نے ان سے کہا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں ذبح کر.میرا کامل یقین ہے اور میں نے متواتر یہ بات بیان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے قرآن کریم سے ثابت کرسکتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رؤیا میں جو یہ دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اس سے مراد ظاہری ذبح کرنا نہیں تھا بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ ایک وقت آپ کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادیٔ غیر ذی زرع میں جا کر چھوڑ آئیں جہاں نہ پینےکے لئے پانی ہو اور نہ کھانے کے لئے غلّہ.ایک جنگل اور وہشت ناک بیابان میں جہاں ہر وقت اس بات کا امکان تھا کہ بھیڑیا آئے اور انہیں کھا جائے.جہاں کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہ تھی.جہاں رہائش کے لئے کوئی مکان نہیں تھا.جہاں سینکڑوں میل تک آبادی کا کوئی نشان تک نہ تھا.حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑنا قتل سے کسی طرح کم نہیں تھا بلکہ زیادہ ہی تھا.قتل کرتے وقت تو مقتول کی ایک منٹ میں جان نکل جاتی ہے مگر یہاں اس بات کا امکان تھا کہ وہ بھوکے اور پیاسے کئی کئی دن تک تڑپ تڑپ اور سسک سسک کر جان دیں.پس میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھی تھی اس میں اسی طرف اشارہ تھا کہ ایک دن تمہیں حکم دیا جائے گا کہ جاؤ اور اسماعیلؑ کو جنگل میں چھوڑ آؤ.کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر جس میں کشش کے کوئی سامان نہیں.جس میں کھانے پینے کے کوئی سامان نہیں جس میں رہائش کا کوئی سامان نہیں اپنا گھر بنائے.اور پھر اس گھر کو ترقی دے کر ایک بستی کی شکل دے اور اس بستی میں ایک ایسی قوم پلتی چلی جائے جس میں اس کا آخری نبی دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث ہو.اس غرض کے لئے خدا تعالیٰ نے ایک جنگل کو چنا اور اس لئے چنا تا وہ خطّہ بیرونی دنیا کے تعیش سے محفوظ رہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عرب میں بت پرستی بھی تھی، بے دینی بھی تھی، بے حیائی بھی تھی اور وہ قوم شرک کے انتہا کو پہنچ چکی تھی مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انسانیت کا جوہر جیسے عرب میں قائم تھا ویسا دنیا میں اور کہیں قائم نہیں تھا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مکہ کے لوگ ایک جنگل میں پڑے ہوئے تھے اور دنیوی تعیش کے سامانوں سے بہت دور تھے.بے شک ان میں بعض دولتمند بھی تھے مگر دنیا کی دولت کے مقابلہ میں ان کی دولت ایسی ہی تھی جیسے کسی احمدی کے پاس اگر لاکھ دو لاکھ روپے ہوں تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا امیر سمجھ لیتا ہے حالانکہ یورپ کے کئی کارخانہ دار ایسے ہیں جن کے ملازموں کے ملازموں کے پاس اس سے زیادہ دولت ہوتی ہے.مکہ کی دولت بھی اس وقت کی معلومہ دنیا کی دولت کے مقابلہ میں بالکل حقیر تھی اور یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت ہوا.اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مکہ میں ایک ایسی قوم بسا دے جو دولت مند دنیا اور عیش والی دنیا سے الگ رہتے ہوئے انسانی جوہروں کو قائم رکھ سکے.
Page 294
چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ یہی تھا کہ آپؐ کو عرب قوم مل گئی جس نے قربانی اور ایثار کا وہ نمونہ دکھایا جس کی مثال دنیا کے پردہ پر نہیں مل سکتی.انہوں نے جس رنگ میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے اس کی مثال دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی.اس طرح وہ قوم اسلام کے پھیلنے اور اس کی اشاعت کا ایک ذریعہ بن گئی.مگر اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں.بہرحال خانۂ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت اور اپنی اولاد کو وہاں بساتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر دی کہ خدا ایک نبی کو میری اولاد میں مبعوث کرے گا جو دنیا کے لئے مرجع ہو جائے گا اور جب انہوں نے دعا کی کہ الٰہی دنیا کے چاروں طرف سے لوگ یہاں آئیں اور حج کریں اور عبادت اور ذکر الٰہی میں اپنا وقت گذاریں اور تیرا نام بلند کریں اور تسبیح و تحمید کریں تو کیاا نہیں طاقت حاصل تھی کہ وہ لوگوں کو کھینچ لاتے.وہ تو خود اپنی بیوی اور بچے کو وہاں مرنے کے لئے چھوڑ گئے تھے انہوں نے کسی اور کو کیا لانا تھا مگر پھر خدا نے مکہ کی آبادی کے کیسے سامان کئے اور ان کی دعا کو کس حیرت انگیز رنگ میں پورا فرمایا.حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چلے گئے تو چند دنوں کے بعد پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے ماں سے اپنے بچہ کی حالت دیکھی نہ گئی تو انہوں نے صفا و مروہ پر چڑھ کر دیکھنا چاہا کہ شاید ادھر ادھر کوئی آدمی نظر پڑ جائے اور وہ ان کے لئے پانی کا انتظام کر دے یا پانی کا کچھ پتہ دے مگر وہاں آدمی کہاں؟ آخر جب بہت بے تاب ہو گئیں تو انہیں کسی کی آواز سنائی دی.اس پر انہوںنے بلند آواز سے کہا اے خدا کے بندے تو جو کوئی بھی ہے میں تجھے قسم دیتی ہوں کہ اگر تجھے پانی کا پتہ ہے تو مجھے بتا کیونکہ میرا بچہ پیاسا مر رہا ہے اس کے جواب میں اس آواز دینے والے نے کہا.ہاجرہ میں خدا کا فرشتہ ہوں جا اور دیکھ کہ خدا نے اسماعیلؑ کے قدموں کے نیچے پانی کا ایک چشمہ پھوڑ دیا ہے.چنانچہ وہ آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ واقعہ میں زمین میں سےایک چشمہ پھوٹ رہا ہے.یہی چشمہ زمزم کہلاتا ہے اور اسی تبرّک کی وجہ سے لوگ اس کا پانی دور دور لے جاتے ہیں بلکہ بعض لوگ وہاں اپنا کفن لے جاتے اور زمزم کے پانی سے گیلا کر کے لے آتے ہیں.پھر جُرہم قبیلہ وہاں سے گذرا اس قبیلہ کے آدمی چونکہ اسی راستہ سے یمن میں تجارت کے لئے جاتے تھے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان میں سے بعض مر جاتے تھے.جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی موجود ہے تو انہوں نے خواہش کی کہ یہاں ایک درمیانی پڑاؤ بنا لیا جائے چنانچہ جُرہم قبیلہ کا رئیس حضرت ہاجرہؓ کے پاس آیا اور اس نے درخواست کی کہ ہمیں یہاں بسنے کی اجازت دی جائے ہم آپ کی رعایا بن کر رہیں گے.حضرت ہاجرہؓ نے اس کی اس درخواست کو منظور فرما لیا اور اس طرح وہ ایک درمیانی پڑاؤ بن گیا جہاں جُرہم قبیلہ کے اور بھی کئی لوگ رہنے لگ گئے.رفتہ رفتہ
Page 295
اس پڑاؤ نے ایک گاؤں کی شکل اختیار کر لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ کی ایک لڑکی سے شادی کرلی(تفسیر جامع البیان زیر آیت رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ....).بھلا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جنگل میں جہاں سینکڑوں میل تک آبادی نہ تھی کہاں سے بیوی لانی تھی.خدا نے ہی یہ سامان کیا کہ وہاں جُرہم قبیلہ کا ایک گاؤں بسا دیا.اس طرح ان کو بیوی بھی مل گئی اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا.مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ آباد کیا تھا اس وقت کون کہہ سکتا تھا کہ یہ مکہ کسی دن شہر بن جائے گا.کون کہہ سکتا تھا کہ لوگ یہاں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گذاریں گے.کون کہہ سکتا تھا کہ یہ شہر ہمیشہ محفوظ رہے گا اور اللہ اسے امن والا بنائے گا.اس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے یہ تمام باتیں ناممکن تھیں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مکہ شہر بنے گا.کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مکہ محفوظ رہے گا.مگر اصحاب الفیل کے حملہ کے وقت وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مکہ ایک شہر بنے گا اور شہر بھی ایسا جو دشمن کے حملہ سے محفوظ رہے گا.اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر کے دکھا دیا.مگر سوال یہ ہے کہ اصحاب الفیل کو اس وقت تک کس نے حملہ کرنے سے روکے رکھا تھا آخر کون سی طاقت تھی جو اس عرصۂ دراز میں مکہ کا محافظ رہی حضرت ابراہیم ؑ اور اصحاب الفیل کے واقعہ کے درمیان کوئی ۲۸ سو سال کا فرق تھا.یا بعض روایتوں کے لحاظ سے ۲۲ سو سال کا فرق تھا.دو ہزار دو سو یا دو ہزار آٹھ سو سال تک مکہ پر کوئی حملہ نہیں کرتا.دو ہزار دو سو سال تک مکہ کے گرانے کی خواہش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی.دو ہزار دو سو سال تک خانۂ کعبہ کو منہدم کرنے کا جوش کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتا نہ کسی یہودی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نہ کسی عیسائی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے نہ کسی اور حکومت کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے.اس عرصہ میں ثمود کی حکومت آئی، عاد کی حکومت آئی.یہ بڑی بڑی حکومتیں تھیں اور ان کی طاقت بہت زیادہ تھی مگر کسی کو یہ خیال پیدا نہ ہو اکہ وہ خانۂ کعبہ پر حملہ کرے لیکن ادھر ربیع الاوّل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور ادھر دو ماہ پہلے محرم میں ابرہہ حملہ کر دیتا ہے اور اس وقت خدا یہ نشان ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیتا ہے.اتنی مدت تک کسی کو خانۂ کعبہ پر حملہ کرنے کا خیال نہ آنا اور اس وقت آنا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے بتاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے اس وقت آخری حملہ تھا تاکہ پیشتر اس کے کہ اس انسان کا ظہور ہو جو دعائے ابراہیمی کے ماتحت پیدا ہونے والا تھا یہ جگہ ہی مٹا دی جائے.اور ابراہیمی پیشگوئی کا دنیا میں ظہور نہ ہو.بہرحال اس پیشگوئی کا پورا ہونا اور ایسے حالات میں پورا ہونا جو بالکل مخالف تھے اور ایسے وقت میں پورا ہونا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے بتاتا ہے کہ اس پیشگوئی کی ایک کڑی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں
Page 296
تھی اور اسی نے مخالف حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم الشان پیشگوئی کو پورا کیا.دعا ئے ابراہیمی میں صاف طور پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ الٰہی تو میری اولاد میں سے ایک ایسا انسان مبعوث کر جو دنیا کو ہدایت دینے والا ہو اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خانۂ کعبہ کو محفوظ رکھے.یہ دونوں دعائیں اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت کے ماتحت ایک ہی وقت میں پوری ہوتی ہیں.محرم میں خانۂ کعبہ کو برباد کرنے والا دشمن اٹھتا ہے اور ربیع الاوّل میں وہ شخص پیدا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ میں دعائے ابراہیمی کا مصداق ہوں مگر ۲۲ سو سال تک نہ کسی نے خانۂ کعبہ پر حملہ کیا اور نہ کسی نے یہ کہا کہ میں دعائے ابراہیمی کا مصداق ہوں.کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو تم اتفاق کہہ لو مگر کیا ابرہہ کے حملہ کو بھی کوئی اتفاق کہہ سکتا ہے.یقیناً اگر تعصب سے کام نہ لیا جائے تو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو اتفاق کہا جا سکتا ہے اور نہ ابرہہ کے حملہ کو اتفاق کہا جا سکتا ہے بلکہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے منشا اور اس کے ازلی فیصلہ کے مطابق ہوا.پیشگوئی کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا.حالات قطعی طور پر مخالف تھے اور کوئی انسان محض اپنی عقل سے قیاس کر کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پیشگوئی پوری ہو جائے گی.مگر ناممکن حالات کو ممکن بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو پورا کر دیا.اگر اس دنیا میں ایسے نظارے نظر آسکتے ہیں تو کیا اس خدا کی بتائی ہوئی وہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہو سکتیں جو اگلے جہان سے تعلق رکھتی ہیں.اگر ان پیشگوئیوں کا پورا ہونا ممکن ہے تو اگلے جہان سے تعلق رکھنے والی پیشگوئیوں کا پورا ہونا کیوں ممکن نہیں.غرض اللہ تعالیٰ نے ہُـمَزَۃ اور لُمَزَۃ کے ساتھ اس سورۃ کو جوڑ کر اس اعتراض کو ردّ کیا ہے جو کفار کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ اگلے جہان کے متعلق جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہم کس طرح مان لیں.اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دعائے ابراہیمی کون سی ممکن تھی.اسماعیلؑ کا موت سےبچ جانا کون سا ممکن تھا.خانۂ کعبہ کا بن جانا اور سارے عرب کی توجہ کا اس کی طرف پھر جانا کون سا ممکن تھا.۲۸ سو سال کے بعد ایک جرار لشکر کے دل میں خانۂ کعبہ پر حملہ کرنے اور اسے گرا دینے کا احساس پیدا ہونا کون سا ممکن تھا.اس دشمن کا تباہ ہونا کون سا ممکن تھا اور پھر اس دشمن کی تباہی کے عین دو ماہ بعد اس شخص کا پیدا ہوجانا جس کی خاطر خانۂ کعبہ کو بسایا گیا تھا کون سا ممکن تھا.اگر یہ ساری ناممکن باتیں ممکن ہو گئی ہیں تو اگلے جہان کی باتوں پر تم کیا اعتراض کرتے ہو.جس خدا نے یہ باتیں پوری کی ہیں وہی اگلے جہان کی باتوں کو بھی پورا کردے گا.غرض قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ اس دنیا کی خبروں اور اگلے جہان کی خبروں کو ملا کر بیان کرتا ہے.
Page 297
اسی طرح جزا و سزا اور تبشیر و انذار کی خبروں کو بھی ملا کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ قریب الفہم ہو جائیں مثلاً اگلے جہان کی دوزخ اور اگلے جہان کی جنت کی حقیقت انسانی سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک وہ اس جہان سے تعلق رکھنے والی انذاری خبروں اور بشارتوں کو پورا ہوتے نہ دیکھ لے.جب وہ اس جہان سے تعلق رکھنےو الی خبروں کو پورا ہوتے دیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ ناممکن باتیں ممکن ہو گئی ہیں تو اگلے جہان سے تعلق رکھنے والی خبریں بھی ضرور پوری ہو کر رہیں گی.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) تفسیر.بسم اللہ مضامین سورۃ کےلئے بطور کنجی کے بسم اللہ کی آیت تمام سورتوں میں مشترک ہے جو ہر سورۃ سے پہلے آتی ہے.میری تحقیق کے مطابق بسم اللہ مضامین سورۃ کھولنے کی کنجی ہے اور اس میں ایسے گُر بتائے گئے ہیں جن سے اگلی سورۃ کے مضامین خود بخود کھل جاتے ہیں.بڑی چیز جو بسم اللہ کے ذریعہ ظاہر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر سورۃ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوتی ہے جو غیر معمولی ہوتی ہے مثلاً یا وہ غیر معمولی ہوتی ہے عقیدہ کے لحاظ سے یعنی دنیا کے عقائد کچھ اور ہوتے ہیں اور قرآن کریم کوئی اور عقیدہ پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کہہ دیتی ہے کہ یہ غلط ہے.یا وہ غیر معمولی ہوتی ہے آئندہ واقعات کے لحاظ سے یعنی اس میںایسی پیشگوئی ہوتی ہے جو حیرت انگیز ہوتی ہے یا وہ غیر معمولی ہوتی ہے پرانے اخبار کے لحاظ سے یعنی تاریخ کچھ اور کہتی ہے مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں اصل واقعہ یوں ہے یا غیر معمولی ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ دنیوی قانونِ قدرت جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے یہ بات سائنس کے خلاف کہہ دی ہے.بہرحال کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات اس میں آجاتی ہے.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہرسورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کو رکھا ہے یعنی میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بغیر کسی محنت اور کوشش کے اور بغیر کسی استحقاق کے سامان مہیا کرتا ہے.پھر وہ ایسا خدا ہے کہ جب کوئی شخص اس کے پیدا کردہ سامانوں سے کام لیتا ہے تو وہ اس کی کوشش کا بہتر سے بہتر بدلہ دیتا ہے.جیسے دنیا میں بعض دفعہ بڑے آدمی کو گواہی کے طور پر پیش کر دیا جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سورۃ سے پہلے اپنے آپ کو بطور گواہ پیش کیا ہے.یہی دیکھ لو
Page 298
پرسوں یہاں چاند نہیں دیکھا گیا.اگر کوئی احمدی دوسرے احمدی سے کہہ دیتا کہ کل روزہ ہو گا تو دوسرا فوراً کہتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے.سارے شہر نے تو چاند نہیں دیکھا پھر روزہ کس طرح ہو گیا.اس پر اگر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ میں خلیفۃ المسیح سے سن کر آیا ہوں تو دوسرا ضرور خاموش ہوجائے گا.کیونکہ وہ سمجھے گا کہ جس انسان کا میرے سامنے نام لیا گیا ہے وہ اتنی بڑی پوزیشن کا ہے کہ وہ غلط بات نہیں کہہ سکتا انہیں ضرور کہیں نہ کہیں سے اطلاع آئی ہو گی.اسی طرح قرآن کریم میں چونکہ غیر معمولی مطالب آتے ہیں اس لئے ہر سورۃ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بِسْمِ اللّٰهِ رکھ دی ہے یہ بتانے کے لئے کہ تم کہو گے کہ یہ تو غیر معمولی باتیں ہیں ہم کیسے مان لیں کہ اس طرح ہو کر رہے گا.ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ان خبروں کا بتانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ہم جو زمین و آسمان کے مالک ہیں یہ خبر دے رہے ہیں اس لئے ان خبروں کی سچائی پر تمہیں بہرحال ایمان رکھنا چاہیے.یہی حکمت ہے جس کی بنا پر ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ رکھ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم کو اگر اس میں کوئی غیر معمولی یا ناممکن بات نظر آئے یا آئندہ کے متعلق کوئی پیشگوئی ہو جس کا پورا ہونا بظاہر مشکل نظر آتا ہو تو تم اس کو غلط مت سمجھو اس لئے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے.یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے.دنیا کی اور الہامی کتب میں سے ہرکتاب الٰہی ہونے کا تو دعویٰ کرتی ہے مگر وہ کتاب کے ہر ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرار نہیں دیتی.عیسائی خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کہ انجیل میں فلاں فلاں بات غلط ہے(Encyclopedia Biblica, Under word "Text and Versions")اور پھر کہتا ہے کہ انجیل خدا کی کتاب ہے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا.ایک طرف تو تم انجیل کی بعض باتوں کو غلط قرار دیتے ہو اور دوسری طرف اسے الٰہی کتاب کہتے ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ انجیل صرف اپنی مجموعی حیثیت میں خدا کی کتاب ہے.یہ نہیں کہ اس کا ہر ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.اسی طرح یہودی اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کہ بائبل کی فلاں فلاں بات غلط ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ بائبل خدا کی کتاب ہے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں ایسا متضاد دعویٰ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بائبل بحیثیت مجموعی خدا کی طرف سے ہے یہ نہیں کہ اس کا ہر ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے.ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ رکھنے کی وجہ اس کے مقابلہ میں قرآن کریم کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس نے ہر ٹکڑا سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ نازل کر کے یہ دعویٰ پیش کیا ہے کہ اس کا ہر ٹکڑا میری طرف سے ہے یہ بھی میری طرف سے ہے اور وہ بھی میری طرف سے ہے تا کوئی شخص بائبل یا انجیل کی طرح یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں ٹکڑا خدا کی طرف سے نہیں بلکہ نعوذباللہ انسانوں نے اس میں ملا دیا ہے گویا بِسْمِ اللّٰهِ نے قرآن کریم کے ہر ٹکڑے پر مہر
Page 299
لگا دی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ کہ اگر کوئی ایک ٹکڑا بھی غلط نکلے تو یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی.بائبل پر ایمان رکھنے والا کہہ دیتا ہے کہ بائبل کا جو حصہ پورا ہو رہا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور جو حصہ پورا نہیں ہو رہا یہ انسانوں کی طرف سے ہے.مگر قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کتاب کا کوئی ایک ٹکڑا بھی پورا نہیں ہوتا تو تم سمجھ لو کہ ساری کی ساری کتاب خدا کی طرف سے نہیں.غرض بِسْمِ اللّٰهِ نے قرآن کریم کے ہرٹکڑے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ڈال دی ہے اور بار بار وہ اس ذمہ داری کا اظہار کرتا ہے.بے شک بائبل بھی خدا تعالیٰ کی کتاب ہے مگر اس کے باوجود بائبل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں ایسے حصے ہیں جو انسانوں نے اپنے ہاتھ سے اس میں ملا دیئے ہیں.اسی طرح انجیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے مگر اس کے باوجود اس میں ایسے ٹکڑے بھی ہیں جن کے متعلق عیسائی کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں.یہی مشکل قرآن کریم کے متعلق بھی پیش آسکتی تھی اگر ایک دفعہ ہی قرآن کریم میں بِسْمِ اللّٰهِ آتی تو ہو سکتا تھا کہ بعض مسلمان اپنی بے ایمانی میں یہ کہہ دیتے کہ فلاں ٹکڑا خدا کی طرف سے نہیں.بعض انسانوں نے اس میں ملا دیا ہے.اس نقص کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر ٹکڑا سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ نازل کر دی ہے اور اس طرح بتایا ہے کہ قرآن کریم سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.بائبل کی اگر ایک آیت غلط ثابت ہو جائے تو یہودی یہ نہیں مانے گا کہ ساری بائبل غلط ہے انجیل کی اگر ایک آیت غلط ثابت ہو جائے تو عیسائی یہ نہیں مانے گا کہ ساری انجیل غلط ہے.لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہےکہ ہم دنیا کے سامنے یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اس کا ایک ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.اس کی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بڑی سے بڑی سورۃ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے.اگر کوئی ایک ٹکڑا بھی غلط ثابت ہو جائے تو سمجھ لو کہ سارا قرآن غلط ہے خدا نے اسے نازل نہیں کیا.یہ کتنا عظیم الشان دعویٰ ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے.اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی الہامی کتاب نہیں ٹھہر سکتی.دنیا میں لوگ اپنی ذمہ داریاں کم کیا کرتے ہیں مگر قرآن کریم نے بار بار بِسْمِ اللّٰهِ نازل کر کے اپنی ذمہ داریوں کو بہت بڑھا لیا ہے اگر ایک دفعہ بِسْمِ اللّٰهِ آتی تو خیال کیا جا سکتا تھا کہ کچھ ٹکڑے ایسے بھی ہوں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوں مگر ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کوئی ٹکڑا بھی ایسا نہیں جس کی صداقت کی ذمہ داری ہم نہ لیتے ہوں.اس لئے کسی ایک ٹکڑے کا غلط ہونا درحقیقت سارے قرآن کا غلط ہونا ہے.مگر کوئی ایک ٹکڑا بھی ایسا ثابت نہیں کیا جا سکتا جو غلط ہو.اور جس کی صداقت دنیا پر واضح نہ کی جا سکتی ہو.غرض یہ آیت قرآن کریم کے مشترک مضامین کی کنجی اور اس کے ہر ٹکڑا کے خدا کی طرف سے نازل ہونے کی ایک بیّن دلیل ہے.
Page 300
بِسْمِ اللّٰهِ میں توکّل کا سبق بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ میں اسلامی عقیدہ کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے.اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ خدا کا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے خدا کرتا ہے.کوئی چیز خدا تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں اور کسی بات میں خدا تعالیٰ کسی دوسرے کی امداد کا محتاج نہیں.ہر چیز جو ماسوی اللہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی.اسی کو عربی زبان میں توکّل کہتے ہیں.یعنی اس عقیدہ کے مطابق انسانی عمل کا نام اسلامی اصطلاح میں توکّل ہے.پس بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ میں توکّل علی اللہ کی تفسیر بیان کی گئی ہے.اس کے معنے یہ ہیں کہ ہم خدا سے مدد مانگتے ہوئے ایسے خدا سے مدد مانگتے ہوئے جس نے سب کے سب سامان بغیر کسی محنت اور کوشش اور تدبیر کے مہیا کر کے دیئے ہیں اور جو ان سامانوں سے کام لینے پر پھر اچھے سے اچھا اور ہمیشہ اور بار بار نتیجہ خیز بدلہ دیتا ہے اس کام کو شروع کر تے ہیں یہ مختصراً ترجمہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کی تفسیر کی جائے تو اسی پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں گویا اس چھوٹی سی آیت میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ حال خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے کیونکہ جب انسان کہتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ میں خدا سے مدد مانگتا ہوں تو اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ یہ زمانہ جس میں مَیں ہوں اور کام کرنا چاہتا ہوں خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے.اگر حال خدا تعالیٰ کے اختیا رمیں نہیں تو وہ مدد کس سے مانگتا ہے.مدد اسی سے مانگی جاتی ہے جس کے قبضہ و تصرف میں حال کا زمانہ ہو پس اگر میں کام کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں تو درحقیقت میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں خدا تعالیٰ کو طاقت حاصل ہے پھر اَلرَّحـمٰن کا لفظ آتا ہے.یعنی میں اس سے مدد مانگتا ہوںجو رحمٰن ہے.رحمٰن کے معنے ہیں بغیر کوشش، محنت اور خدمت کے ہر قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا(مفردات).گویا رحمانیت کے ماتحت وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو بغیر کسی محنت اور کوشش کے انسانوں کو ملتی ہیں.رحمانیت میں آسمان کی پیدائش بھی شامل ہے، رحمانیت میں زمین کی پیدائش بھی شامل ہے، رحمانیت میں پانی بھی شامل ہے، رحمانیت میں ہوا بھی شامل ہے، رحمانیت میں انسان کا اپنا جسم بھی شامل ہے، رحمانیت میں اس کے تمام قویٰ مثلاً ناک، کان اور آنکھیں وغیرہ بھی شامل ہیں.رحمانیت میں حیوانات بھی شامل ہیں، رحمانیت میں جمادات بھی شامل ہیں، رحمانیت میں چاند اور ستارے وغیرہ بھی شامل ہیں.غرض جو کچھ بھی اس دنیا میں پایا جاتا ہے جس کے بنانے میں ہم نے محنت نہیں کی وہ رحمانیت کا نتیجہ ہے اور ہر چیز جس کےبنانے میں ہم نے ہاتھ ہلایا ہے وہ رحیمیت ہے.دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں یا تو ایسی چیزیں ہیں جن کےبنانے میں انسان نے حصہ نہیں لیا.یا ایسی چیزیں ہیں جن کے بنانے میں انسان نے حصہ لیا ہے.وہ چیزیںجن کے بنانے میں انسان نے حصہ
Page 301
نہیں لیا وہ رحمانیت کی صفت کے ماتحت آتی ہیں.ان کے لئے کیوں رحمانیت کا لفظ بولا گیا ہے؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ کچھ چیزیں خدا نے بنائی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن میں بندوں کی محنت اور ان کی کوشش کا دخل ہے.کیوں خدا نے یہ نہیں کہا اور لفظ ِ رحمٰن سے اس مفہوم کو ادا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ لفظ بولے جاتے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے پیدا کی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بندوں نے بنائی ہیں تو ان الفاظ سے یہ نتیجہ تو نکلتا کہ ان پیدا کی ہوئی اشیاء میں سے کچھ چیزیں خدا کی بھی ہیں مگر یہ نتیجہ نہ نکلتا کہ جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں وہ سب کی سب انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہیں یہ سوال بہرحال باقی رہ جاتا کہ وہ چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں وہ کسی فائدہ کے لئے ہیں یا ان میں سے کچھ بے فائدہ بھی ہیں.مگر رحمانیت کے لفظ نے بتا دیا کہ وہ سب کی سب ہمارے فائدہ کے لئے ہیں.رحم کا لفظ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے بولا جاتا ہے یوں ہی نہیں بولا جاتا.مثلاً اگر سورج چمک رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بڑا رحم کر رہا ہے کیونکہ رحم میں دو باتوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے.اوّل دوسرے کے فائدہ کا کام کرنا.دوم اس نیت سے کرنا کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے.فرض کرو کوئی شخص جا رہا ہے اور اس کی جیب سے اتفاقاً ایک پیسہ گر گیا ہے کسی اور نے اٹھا لیا ہے اب اسے فائدہ تو پہنچ گیا مگر کیا کوئی شخص اس وجہ سے کہ اس کے پیسہ سے دوسرے نے فائدہ اٹھا لیا ہے یہ کہے گا کہ وہ بڑے رحم کرنے والے انسان ہیں.پس رحم کے معنوں میں صرف یہی بات شامل نہیں ہوتی کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے بلکہ اس میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت بھی ہو.پس رحمٰن کا لفظ بول کر بعض زائد امور بیان کئے گئے ہیں جو اس لفظ کے بغیر ادا نہیں ہو سکتے تھے یعنی یہی نہیں کہا گیا کہ خدا نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کے پیدا کرنے میں انسان کا دخل نہیں بلکہ خدا نے ان چیزوں کو پیدا ہی انسان کے فائدہ کے لئے کیا ہے اور اس نیت سے پیدا کیا ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے.رحیم فَعِیْل کے وزن پر ہے اور یہ وزن تواتر اور لمبے زمانہ کی طرف اشارہ کرتاہے اور رحمٰن فَعْلَان کے وزن پر ہے اور وسعت کی طرف اشارہ کرتا ہے.رحیم کے معنے ہیں وہ جو بار بار نتائج پیدا کرتا ہے(لسان العرب).جب رحمانیت کے سامانوں سے انسان فائدہ اٹھالیتا ہے تو رحیم خدا اس کے بار بار نتائج پیدا کرتا ہے مثلاً انسان روٹی کھاتا ہے روٹی کھانے کا یہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر جاتا ہےبلکہ اس کے نتیجہ میں خون پیدا ہوتا ہے جو مہینوں اور سالوں انسانی جسم میں کام کرتا ہے.اسی خون سے اس کے دماغ کو طاقت ملتی ہے، اس کی نظر کو طاقت ملتی ہے، اس کے ذہن کو طاقت ملتی ہے، اس کے کانوں کو طاقت ملتی ہے جو مہینوں اور سالوں اس کے کام آتی ہے.پھر اسی میں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے جس سے اس کی نسل پیدا ہوتی ہے.پھر اس نسل سے اگلی نسل اور اگلی نسل سے اور اگلی نسل پیدا ہوتی ہے.گویا
Page 302
ایک ایک فعل تواتر سے نتائج پیدا کرتا ہے یہ رحیمیت ہے.اگر دنیا میں صرف یہی سلسلہ ہوتا کہ جب کوئی شخص کام کرتا تو اسی وقت اس کا ایک نتیجہ پیدا ہو جاتا تو ہم اس کو بدلہ تو کہہ سکتے تھے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے تو اپنی اجرت لے لیتا ہے مگر ہم اسے رحیمیت نہیں کہہ سکتے تھے رحیمیت کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پنشن ہوتی ہے.لوگ ملازمت کرتے ہیں تو انہیں اس کا بھی ایک بدلہ مل رہا ہوتا تھا.مگر اس کے ساتھ ہی ان کے کھاتے میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ آئندہ اس کام کا متواتر نتیجہ پیدا ہو گا چنانچہ اگر کوئی دس یا پندرہ سال ملازمت کرتا ہے تو وہ تنخواہ کے 1/10 حصہ کی پنشن کا حقدار ہو جاتا ہے.بیس سال گذر جائیںتو 1/3 پنشن کا حقدار ہو جاتا ہے.پچیس سال گذر جائیں اور وہ ڈاکٹری سارٹیفکیٹ بھی پیش کر دے تو اسے نصف پنشن مل جاتی ہے اور اگر تیس سال گذر جائیں تو بغیر ڈاکٹری سارٹیفکیٹ کے ہی وہ پوری پنشن کا حقدار بن جاتا ہے.یہ چیز ہے جو رحیمیت کے مشابہ ہے یعنی کام کا بدلہ نقد ہی نہیں ملا بلکہ آئندہ کے لئے اور نیک نتائج کی بنیاد بھی ساتھ ہی رکھ دی گئی.پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی رحیمیت اور خدا تعالیٰ کی رحیمیت میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان بدلہ دیتا ہے تو یہ سمجھ کر دیتا ہے کہ اس شخص نے کچھ سالوں کے بعد مر جانا ہے اگر اسے پتہ لگ جائے کہ اس شخص نے کبھی نہیں مرنا تو وہ کبھی اسے پنشن نہ دے.مگر چونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس نے ضرور چند سالوں کے اندر اندر مر جانا ہے اس لئے وہ پنشن دے دیتا ہے لیکن خدا کو نہ صرف یہ پتہ ہے کہ انسان نہیں مرے گا بلکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں انسان کو ماروں گا نہیں بلکہ اسے ابدی زندگی دوں گا.گویا یہی نہیں کہ وہ اتفاقی طور پر اس حادثہ کو برداشت کر لیتا ہے بلکہ وہ انسان کے زندہ رہنے اور اس کی دائمی حیات کے خود سامان مہیا کرتا ہے اس لئے خدا کی رحیمیت کی شان اور ہے اور انسان کی رحیمیت کی شان اور ہے.بہرحال بِسْمِ اللّٰهِ حال پر، رحـمٰن ماضی پر اور رحیم کا لفظ مستقبل پر دلالت کرتا ہے اور یہ تینوں الفاظ بتاتے ہیں کہ تمام کے تمام کاموں میں تقدیر الٰہی انسان کے ساتھ وابستہ ہے.بِسْمِ اللّٰهِ میں چھوٹی سی تدبیر شامل ہے یعنی انسان کہتا ہے میں خدائی مدد سے یہ کام شروع کرتا ہوں.گویا ارادہ انسان کا اپنا ہوتا ہے.اگر میرا ارادہ کسی کام کے متعلق نہ ہو تو میں یہ کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا کی مدد سے فلاں کام شروع کرتا ہوں.بہرحال اس میں کچھ بندے کا بھی دخل ہوتا ہے.اس کے بعد رحمانیت کا دائرہ ہے جو خالص خدا سے تعلق رکھتا ہے.اور رحیمیت میں تھوڑا سا کام بندہ کرتاہے اورغیرمنتہیٰ نتیجہ خدا پیدا کرتا ہے گویا تدبیر اور تقدیر دونوں سے مل کر یہ دنیا چلتی ہے اور بِسْمِ اللّٰهِ ہم کو بتاتی ہے کہ تقدیر اور تدبیر آپس میں اس طرح الجھی ہوئی ہیں کہ ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا.آگے انسان کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے اس کے کام بڑے اور چھوٹے ہوتے چلے
Page 303
جاتے ہیں.ایمان کامل میں تقدیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اور تدبیر کا پہلو کمزور ہوتا ہے جیسے رحمانیت خالص خدا کی تھی اسی طرح جو انسان خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس کی زندگی کے کاموں میں بھی تقدیر زیادہ اور تدبیر کم نظر آتی ہے.وہ بے شک تدبیر بھی کرتاہے مگر اس کے نتائج اس کی تدبیر سے بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى (الانفال:۱۸) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھائے اور مٹھی بھر کر انہیں دشمن کی طرف پھینکا(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام رمی الرسول للمشـرکین بالحصباء) مگر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ مٹھی بھر کنکروں سے کہاں نکل سکتا تھا.دس ہزار آدمی بھی اگر ایک ایک مٹھی کنکروں کی پھینکیں تو ان کا وہ نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھینکے ہوئے مٹھی بھر کنکروں نے پیدا کر دیا آپؐ نے ادھر مٹھی بھر کر کنکر پھینکے ادھر ایک ہزار تجربہ کار لشکر جو سامنے کھڑا تھا بے کار ہو گیا.کنکر بے شک آپؐنے ہی پھینکے مگر جب آپؐ نے کنکر پھینکے تو خدا تعالیٰ نے کہا اب آگے بندے کا کام نہیں بلکہ میرا کام ہے.چنانچہ کنکروں کو دشمن تک پہنچانے کے لئے ہوا کی ضرورت تھی خدا نے ہوا سے کہا کہ چلو اور کنکروں کو دشمن کی آنکھوں میں ڈالو.پھر مٹھی بھر کنکر صرف دو چار کی آنکھوں میں پڑ سکتے تھے مگر خدا نے زور کی ہوا چلا کر میدان کی ریت اور کنکر اٹھا اٹھا کر دشمن کی آنکھوں میں ڈالنے شروع کر دیئے.گویا مٹھی بھر کنکر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکے اور کروڑوں کروڑ کنکر خدا نے پھینکے.جب انسان کوئی چیز پھینکنے کے لئے اپنے ہاتھ ہلاتا ہے تو اس سے کسی قدر ہو امیں ضرور حرکت پیدا ہوتی ہے آپؐکے کنکر پھینکنے سے بھی ضرور ہوا میں حرکت پیدا ہوئی ہو گی مگر اس حرکت سے جو ہوا چلی ہو گی وہ اتنی بھی تو نہیں ہو گی جتنی ایک پھونک مارنے سے پیدا ہوتی ہے.لیکن ادھر آپؐنے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور ادھر خدا نے ہوا سے کہا کہ تم زور سے چلو اور دشمن کو اندھا کر دو.اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمن کو اس کے عزائم میں کلی طور پر ناکام کر دیا.بہرحال اس سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ نشان ظاہر فرمایا اس میں تدبیر کا حصہ بہت کم تھا اور تقدیر کا حصہ بہت زیادہ تھا.یہی حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کاموں کا تھا.یہی حال باقی انبیاء ؑ کے کاموں کا تھا.ان کے کاموں میں بھی تدبیر کم اور تقدیر زیادہ تھی.پھر انبیاء سے نیچے اتر کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں ان کے کاموں کو ہم دیکھتے ہیںتو ان میں بھی تدبیر کم ہوتی ہے اورتقدیر زیادہ ہوتی ہے.لیکن جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے اس میں تدبیر کا پہلو غالب ہوتا ہے جیسے مادی لوگ ہیں یا دہریہ وغیرہ ہیں.میں نے کمزور ایمان والا ان کو اس لئے کہا ہے کہ دہریہ میں بھی کچھ نہ کچھ ایمان ضرور ہوتا ہے کم از کم وہ خدا تعالیٰ کے قانونِ قدرت پر ضرور ایمان رکھتا ہے اس لحاظ سے ہم
Page 304
پورے طور پر کسی کو بے ایمان نہیں کہہ سکتے.کسی کو خدا کے کلام پر ایمان ہوتاہے اور کسی کو خدا تعالیٰ کے قانونِ قدرت پر ایمان ہوتا ہے.پاگل بے شک مستثنیٰ ہوتا ہے وہ قانون قدرت کا بھی لحاظ نہیں کرتااور خدا تعالیٰ کے کلام کا بھی پاس نہیں کرتا.مگر اس کو مستثنیٰ کرتے ہوئے باقی تمام مادی آدمی آدھی بات پر ضرورایمان رکھتے ہیں یعنی گو انہیں خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان نہیں ہوتا مگر وہ اس کے فعل پر ضرور ایمان رکھتے ہیں بلکہ بعض دفعہ مومنوں سے بھی زیادہ وہ خدا تعالیٰ کےفعل پر ایمان کا اظہار کرتے ہیں.بہرحال کمزور ایمان والے اور مادی اور دہریہ انسانوں کے کاموں پر تدبیر غالب ہوتی ہے، اور تقدیر کا حصہ کم ہوتاہے گو ہوتا ضرور ہے مثلاً جب وہ کھانا کھاتا ہے تو ان کا معدہ کھانے کو ہضم کرتا ہے اور یہ تقدیر ہی کا فعل ہے اس نے تو اتنا ہی کیا تھا کہ ارادہ کیا اورمنہ میں لقمہ ڈال لیا.باقی جو کچھ کام کیا وہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہی نے کیا.حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دہریہ سے دہریہ بھی خدا تعالیٰ کی تقدیر سے باہر نہیں ہوتا.ایک دہریہ کی زبان پر بھی میٹھا رکھ دو تو باوجود اس کے کہ وہ خدا کو گالیاں دیتا ہو گا مگر خدا کو گالیاں دینے والی زبان بھی اس میٹھے کو میٹھا ہی چکھے گی غرض تقدیر ہر ایک شخص کے کام کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے مگر تدبیر کا پہلو غالب ہوتا ہے اور تقدیر کا پہلو کمزور ہوتاہے سوائے اہل اللہ کے کہ ان کا حساب اس کے الٹ ہوتا ہے.ان دو کےعلاوہ جو درمیانی درجہ کا مومن ہوتا ہے خواہ وہ کلامِ الٰہی کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو جیسے عیسائی کہ وہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ عیسائی مذہب کو تسلیم کرتے ہیں حالانکہ وہ اسلام پر ایمان نہیں لائے.اسی طرح یہودی بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ یہودی مذہب کو تسلیم کرتے ہیں.ہندو بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں کیونکہ وہ ہندو مذہب کو تسلیم کرتے ہیں.ان لوگوں کے لئے خواہ وہ کلام الٰہی کو ماننے والے ہوں یا نہ ہوں دونوں چیزوں کا امتزاج ہوتا ہے اور تقدیر اور تدبیر ان کے لئے ملی ہوئی ہوتی ہیں.ایسے لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں خواہ وہ سچے مذہب پر نہ ہوں جیسے عیسائی اور یہودی اور ہندو سب دعاؤں سے کام لیتے ہیں اور تدبیر سے بھی کام لیتے ہیں گویا تقدیر اور تدبیر کا ایک لطیف امتزاج ان دونوں کے لئے ہوتا ہے.غرض مومنِ کامل جو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے اس کے کاموں میں تقدیر کا پہلو غالب ہوتا ہے.اور جو شخص خدا تعالیٰ سے دور چلا جاتا ہے اس کے کاموں میں تدبیر کا پہلو غالب ہوتاہے اور جو درمیانی درجہ کا آدمی ہوتا ہے اس کے کاموں میں تقدیر اور تدبیر دونوں ملی ہوئی ہوتی ہیں.یہ مضمون ہے جس کو بِسْمِ اللّٰهِ ظاہر کرتی ہے اور چونکہ ہر سورۃ سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ آتی ہے.اس لئے جب انسان بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھتا ہے تو وہ اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ آگے
Page 305
مضمون بیان ہو رہا ہے اس سے میں اپنے ایمان اور عرفان کے لحاظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا.اگر وہ اعلیٰ درجے کا ایمان رکھنے والا ہے تو وہ اس سے ایسا فائدہ اٹھاتا ہے کہ وہ سورۃ اس کے لئے ویسی ہی بن جاتی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نازل ہوئی تھی اور اگر وہ دشمنی کرتا ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتا.ساری کی ساری سورۃ بےکار اور رائیگاں چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے حق میں ضائع ہو جاتی ہے.اور اگر وہ درمیانی درجہ کا مومن ہو تو سورۃ کا مضمون صرف ایک حد تک اسے فائدہ بخشتا ہے پورا فائدہ نہیں دیتا.اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِؕ۰۰۲ (اے محمد صلعم) کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی (استعمال کرنے) والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا.تفسیر.اَلَمْ تَرَ اصل میں اَلَمْ تَرٰی ہے لَمْ جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اگر اس کے آخرمیں یا ہو تو وہ گر جاتی ہے.اسی وجہ سے اَلَمْ تَرٰی کی بجائے صرف اَلَمْ تَرَ رہ گیا.اس کے معنے یہ ہیں کہ کیا تو نے دیکھا نہیں.اصحاب الفیل کے ہلاک ہونے کے وقت کا تاریخ سے تعیّن یہاں دیکھنے سے دل کی آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت کی راہ سے دیکھنا مراد ہے آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہو سکتا(لسان العرب ) کیونکہ جس واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے.کتنا پہلے کا ہے؟ اس بارہ میں اختلاف ہے بعض مورخ کہتے ہیں یہ ستّر سال پہلے کا ہے.بعض مؤرخ کہتے ہیں یہ پچاس سال پہلے کا ہے.بعض مؤرخ کہتے ہیں یہ چالیس سال پہلے کا ہے.بعض مؤرخ کہتے ہیں یہ تیس سال پہلے کا ہے.بعض مؤرخ کہتے ہیں یہ تئیس سال پہلے کا ہے.بعض مؤرخین اسے پندرہ سال پہلے کا قرار دیتے ہیں اور بض مؤرخین اسے دس سال پہلے کا قرار دیتے ہیں(روح المعانی و مـجمع البیان زیر آیت ھذا).لیکن صحیح روایت جس کے قرائن بعض دوسری تاریخوں سے بھی ملتے ہیں یہ ہے کہ درحقیقت یہ اسی سال کا واقعہ ہے جس سال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے(مجمع البیان زیر آیت ھذا) جو تاریخی شہادتیں کثرت سے مل جاتی ہیں اور جن کے قرائن دوسری تاریخوں یا دوسرے ملکوں کی تاریخوں سے بھی ملتے ہیں وہ اسی کی تائید کرتی ہیں.یہ واقعہ محرم میں ہوا تھا جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ربیع الاوّل میں ہوئی ہے(شرح مواھب اللدنیۃ الزرقانی، عام الفیل و قصۃ ابرھۃ) آگے کچھ پیدائش کی تاریخوں کے متعلق اختلاف ہے اور کچھ محرم کی تاریخوں کے
Page 306
متعلق اختلاف ہے.کسی نے محرم کی پہلی تاریخیں قرار دی ہیں اور کسی نے محرم کی آخری تاریخیں قرار دی ہیں.اسی طرح کسی نے ربیع الاوّل کی پہلی تاریخ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بتائی ہے اور کسی نے کوئی اور تاریخ بتائی ہے.اس اختلاف کی وجہ سے اس امر میں بھی اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے دن پہلے ہوا.بعض کہتے ہیں اس حملہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں پچپن دن کا فاصلہ تھا.حافظ دمیاتی کا یہی قول ہے.لیکن سہیلی جو ایک بہت بڑے مؤرخ گذرے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچاس دن پہلے ہوا ہے اور بالعموم اسلامی مؤرخ اور محدث پچاس دن والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں.پھر اس سے اتر کر بعض نے چالیس دن اور بعض نے تیس دن بھی فاصلہ قرار دیا ہے (تفسیـر روح المعانی زیر آیت ھذا ) مگر کثرت سے مؤرخین سہیلی کی اس روایت کو کہ دونوں واقعات میں پچاس دن کا فاصلہ تھا ترجیح دیتے ہیں.پس جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ واقعہ پہلے ہوا ہے خواہ تیس دن پہلے ہوا ہو خواہ تیس سال بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اس لئے تَرَ سے رؤیت قلبی ہی مراد لی جائے گی رؤیت عینی نہیں.پس اَلَمْ تَرَ کے لفظی معنے یہ ہوئے کہ کیا تجھے معلوم نہیں.اس فقرہ کے عام طور پر دو معنے ہو سکتے ہیں.اوّل یہ کہ ہم دوسرے شخص سے پوچھتے ہیں کہ آیا فلاں بات اسے معلوم ہے یا نہیں دوسرے معنے اس قسم کے فقرہ کے یہ ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ بات خوب معلوم ہے.گویا بظاہر نفی کے الفاظ ہوتے ہیں مگر معنے مثبت ہی کے ہیں بلکہ مثبت پر زور دینے کے ہوتے ہیں.اردو میں بھی کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں میں ایسا کر سکتا ہوں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں.گویا اس قسم کا فقرہ بجائے اس کے کہ شک کا اظہار کرے یقین اور وثوق پر دلالت کرتا ہے.اگر ایسا فقرہ کہنے والا کوئی انسان ہو تو کسی کو شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیا اس نے شک کے معنوں میں استعمال کیا ہے یا وثوق کے معنوں میں.لیکن خدا تعالیٰ کے متعلق ہم یہ نہیں خیال کر سکتے کہ نعوذ باللہ اس کے قول کا یہ مطلب ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ تم کو فلاں واقعہ کا علم ہے یا نہیں تم ہی بتاؤ کہ تمہیں اس کا علم ہے یا نہیں.پس یہ فقرہ شک کے معنوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق استعمال ہی نہیں ہوسکتا.کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں اور جب وہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں تو اس کی طرف وہ معنے کبھی منسوب نہیں ہو سکتے جن میں شک و شبہ پایا جاتا ہو.پس اس آیت کے وہی معنے مراد لینے ہوں گے جو یقین اور قطعیت پر دلالت کرتے ہیں.پس اَلَمْ تَرَ کے لفظی معنے گو یہی ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں.مگر درحقیقت اس کا مفہوم اس جگہ یہ ہے کہ تم خوب اچھی طرح سے جانتے بوجھتے
Page 307
اور سمجھتے ہو اور تم سے یہ حقیقت مخفی نہیں ہے.اَلَمْ تَرَ کے متعلق ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی مخاطب تو ساری دنیا ہے.آیا اَلَمْ تَرَ میں بھی ساری دنیا مخاطب ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں یا دشمنانِ اسلام مخاطب ہیں.اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو قرآن کریم ساری دنیا کے لئے ہے خواہ بعض آیات میں براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ مخاطب ہوں مگر اس سورۃ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں خطاب براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے اور پھر آپؐکے توسط سے باقی دنیا مخاطب ہے چنانچہ آگے ہی فرماتا ہے.كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تیرے رب نے کس طرح کیا.یوں تو خدا تعالیٰ سب کا رب ہے مگر جب ایک ایسے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جو عرب اور خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے تو رَبُّكَ کے الفاظ سے یہی سمجھا جائے گا کہ اس میں خطاب خصوصیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہی کیا گیا ہے.غرض اس آیت میں ت اور ک یہ دو ضمائر خطاب کی ہیں.پس تَرَ اور رَبُّكَ یہ دو الفاظ جو اس جگہ آئے ہیں بتاتے ہیں کہ اس واقعہ کا تعلق خصوصیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور اس سورۃ میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کا اصل اور اہم تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے.اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس کا خاص تعلق نہ ہوتا تو رَبُّكَ کہنے کی کیا ضرورت تھی.مثلاً ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے ’’تمہارے خدا‘‘ نے نادر شاہ سے کیا کیا.ہم یہ تو کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے خدا نے نادر شاہ سے کیا کیا مگریہ نہیں کہیں گے کہ ’’تمہارے خدا‘‘ نے اس سے کیا سلوک کیا.کیونکہ تمہارے کا لفظ خاص تعلق کی طر ف اشارہ کرتا ہے.اسی طرح جب خدا نے کہا کہ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تیرے خدا نے اس سے کس طرح کا سلوک کیا تو اس کے معنے درحقیقت یہی ہیں کہ ہم نے اس وقت جو کچھ کیا تھا محض تیرے لئے کیا تھا.ورنہ اگر یہ مفہوم نہ لیا جائے تو اصحاب الفیل کے واقعہ کا علم رکھنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت ہے عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ ایسا واقعہ ہو اہے بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اصحاب الفیل کا واقعہ دیکھا تھا ایسی صورت میں اَلَمْ تَرَ کہنے کے کوئی معنے ہی نہیں بنتے.وہ واقعہ جو اور ہزاروں لوگوں کو معلوم تھا اور جس کو دیکھنے والے بھی کئی زندہ موجود تھے.اسی واقعہ کا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہو گیا تو اس میں آپؐکی خصوصیت کیا رہی.آپؐکی خصوصیت اسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس واقعہ کا آپؐسے کوئی خاص تعلق ہو.اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ میں كَيْفَ استعمال کرنے میں حکمت پھر اس آیت میں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ
Page 308
فَعَلَ رَبُّكَ کے الفاظ ہیں یعنی تیرے رب نے کس طرح کیا.یہ نہیں فرمایا کہ اَلَمْ تَرَ مَا فَعَلَ رَبُّكَ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رب نے کیا کیا.کس طرح کیا اور کیا کیا میں بہت بڑا فرق ہے.اگر صرف یہ بیان کرنا مقصود ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل سے کیا کیا تو كَيْفَ کا لفظ اللہ تعالیٰ اس جگہ استعمال نہ کرتا مگر اس نے كَيْفَ کا لفظ استعمال کیا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاںیہ بیان کرنا مقصود نہیں کہ اصحاب الفیل سے کیا ہوا.بلکہ یہ بتانا مقصود ہےکہ اصحاب الفیل سے جو کچھ ہوا کس طرح ہوا.عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ کلام کے مفہوم میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے.فارابی ایک مشہور مسلمان فلسفی گذرے ہیں جس طرح یورپ میں ہیگل وغیرہ مشہور ہیں اسی طرح مسلمانوں میں فارابی اسی پایہ کے فلسفی تھے.سارا دن فلسفہ اور ادب کی باتوں میں ہی مشغول رہتے تھے.زبان کے لحاظ سے بھی بہت بڑے ادیب تھےاور چوٹی کے زبان دان سمجھے جاتے تھے.ایک دفعہ وہ بازار میں سے گذر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک آٹھ نو سال کا لڑکا حلوا بیچ رہا ہے انہوں نے اس لڑکے سے پوچھا کَیْفَ تَبِیْعُ الْـحَلْوٰی تم حلوا کس طرح بیچتے ہو.اس نے کہا رِطْلًا بِدِرْھَمٍ ایک درہم کے بدلہ میں مَیں ایک پونڈ دیتا ہوں.فارابی نے یہ جواب سنا تو انہوں نے اس کے گلے میں پٹکا ڈال لیا اور شور مچا دیا کہ کتنا بڑا اندھیر ہے عربی زبان کا خون ہو رہا ہے اور کوئی شخص توجہ نہیں کرتا.ادھر لڑکے نے چیخیں مارنا شروع کر دیا.شور سن کر بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے چونکہ وہ آدمی بڑے پایہ کے تھے اس لئے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ لڑکے کو ان کے ہاتھ سے چھڑائے.یوں سمجھ لو جیسے علامہ اقبال یا غالب اپنےز مانہ میں کسی کو پکڑکر شور مچا دیتے کہ اردو زبان کا قتل ہو گیا.ان کے سامنے کون راہ گیر بولنے کی جرأت کر سکتا تھا.اسی طرح یہ واقعہ ہوا لوگ حیران تھے لیکن بات میں دخل نہ دے سکتے تھے.آخر بلدہ کا کمشنر پولیس آیا پہلے تو وہ اس نظارہ کو دیکھ کرگھبرایا.مگر آدمی ہوشیار تھا کہنے لگا حضور اس مجرم کو چھوڑیئے اور ہمارے حوالہ کیجئے ہم اس کو سزا دیں گے پھر اس نے پوچھا کہ حضور اس نے قصور کیا کیا ہے.انہوں نے کہا قصور کا پوچھتے ہو اس سے بڑ ھ کر قصور کیا ہو گا کہ میں كَيْفَ سے سوال کرتا ہوں اور یہ کَمْ کا جواب دیتا ہے.ہماری زبان برباد کر دی گئی اور ہم پر ظلم کیا گیا.حقیقت یہ ہے کہ فارابی تو ایک بچے سے بھی یہ امید رکھتے تھے کہ وہ صحیح عربی بولے مگر مسلمان خدا تعالیٰ سے بھی یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنے کلام میں صحیح عربی الفاظ استعمال کرے.وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تو كَيْفَ کا لفظ استعمال کیا ہے مگر اس کی مراد کَمْ سے ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ كَيْفَ کے لفظ نے مضمون کو ایسی خوبی بخش دی ہے جو اس کی شان کو بہت بڑھا دیتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تمہیں معلوم ہے کہ ان سے
Page 309
کس طرح کیا.یہاں کمیت پر زور دینا مقصود نہیں.یہ مراد نہیں کہ دس مرے تھے یا سو، ہاتھی مرے تھے یا کتے، افسر مرے تھے یا ماتحت، بلکہ ان غیر معمولی حالات کی طرف اشارہ مقصود ہے جن میں ان کی ہلاکت واقعہ ہوئی.خواہ ایک ہی شخص مرا ہو مگر وہ مرا اس طرح کہ دنیا کہتی تھی کہ وہ نہیں مرے گا مگر پھر بھی وہ مر گیا.پس یہاں کمیت کا بتانا مقصود نہیں بلکہ کیفیت کا بتانا مقصود ہے.یعنی غیر معمولی حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کر دیئے گئے.جن حالات کو انسانی عقل سمجھ ہی نہیں سکتی تھی.مگر مفسرین کا بڑا زور اس امر پر ہوتا ہے کہ ان کے سر پر پتھر پڑے اور پاخانہ کی جگہ سے نکل گئے.یا یہ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی بچ کر واپس نہ جا سکا.حالانکہ قرآن اس پر زور ہی نہیں دے رہا.قرآن تو کہتا ہے کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ کیا تم نے دیکھا اور غور کیا کہ تمہارے رب نے کیسے غیر معمولی حالات میں اصحاب الفیل کو تباہ کیا.خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں بڑی موت واقعہ ہوئی.بڑی موت تو بعض دفعہ جہاز کے ڈوبنے سے بھی ہو جاتی ہے.خدا تعالیٰ جس امر پر زور دینا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا ہاتھ دیکھو اور اس امر پر غور کر وکہ جو کچھ کیا تھا میں نے کیا تھا.کسی انسانی ہاتھ کا اس میں دخل نہیں تھا.پس حقیقت اور واقعات پر زور دینا اس جگہ مطلوب نہیں بلکہ اس کے نادر اور مخفی الاسباب ہونے پر زور دینا مقصود ہے.یہ سوال نہیں کہ ابرہہ اور اس کا لشکر سب کا سب مر گئے یا کچھ بچ بھی گئے.بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح مرے.جو بھی مرے ان کے مرنے میں کسی انسانی تدبیر کا دخل نہیں تھا بلکہ محض ہمارے پیدا کردہ حالات کے نتیجہ میں وہ ہلاک ہوا.پس یہاں خدا اپنے فعل کو پیش کر رہا ہے.وہ یہ نہیں بتاتا کہ ابرہہ پر کیسی تباہی آئی.بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس پر کیسے تباہی آئی.وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابرہہ کو ان حالات میں مارا جبکہ دنیا اس کے مارے جانے کا خیال بھی نہ کر سکتی تھی.پس خدا تعالیٰ اس جگہ اپنے فعل پر زور دے رہا ہے اور اس پر زور دے رہا ہے کہ اس نے یہ فعل محض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کیا.پس اس سور ۃ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی قدرت دکھانے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دشمن کے حملہ سے بچانے کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے خانۂ کعبہ کی حفاظت یا اس کا بچنا ایک ضمنی چیز ہے اور ایسی ہی ہے جیسے کسی بڑے آدمی کی دعوت کے ساتھ اس کے نوکر کی بھی دعوت ہو جاتی ہے یا کسی بڑے آدمی کی دعوت ہو تو اس کے پرائیویٹ سکرٹری کو بھی بلا لیا جاتا ہے.پرائیویٹ سکرٹری اپنی ذات میں مقصود نہیں ہوتا بلکہ مقصود وہی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے اعزاز میں دعوت دی جارہی ہوتی ہے.اسی طرح خانۂ کعبہ کی حفاظت اصل مقصود نہیں تھی بلکہ اصل مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تھی.چنانچہ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ تو نے دیکھا تیرے رب نے کس طرح معاملہ کیا.اس
Page 310
میں رَبُّكَ کا لفظ صاف طور پر بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ اس واقعہ سے خانۂ کعبہ کو بچانا اتنا مطلوب نہ تھا جتنا تیری ذات کو بچانا مقصود تھا.اگر خانۂ کعبہ کو بچانا اس واقعہ کا اصل مقصود ہوتا تو یوں فرماتا.اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّ الْکَعْبَۃِ تو نے دیکھا کہ کعبہ کے رب نے کس کس طرح کا معاملہ کیا.ظاہر ہے کہ جب اس نشان میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ تھا تو خدا تعالیٰ کا ہی یہ حق ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے یہ نشان کس کے لئے دکھایا تھا.اگر تو اس نشان میں انسانی ہاتھ ہوتا تو بے شک انسان کہہ سکتے تھے کہ یہ نشان فلاں کے لئے ظاہر ہوا ہے.مگر جبکہ اس میں کسی انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ محض خدا کا ہاتھ ہے.تو اسی کا حق ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس نے یہ نشان کس کے لئے ظاہر کیا تھا.فرض کرو ایک دعوت کرنے والا الف کے اعزاز میں دعوت کرتا ہے تو ب اور ج کا کیا حق ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ دعوت د کے اعزاز میں دی گئی ہے.اگر ب اور ج کوئی ایسی بات کہیں گے تو ہم دعوت کرنے والے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے کس کے اعزاز میں دعوت دی تھی پھر جو کچھ وہ کہے گا وہی فیصلہ کن بات ہو گی.اسی طرح اس آیت میں ایک طرف كَيْفَ فَعَلَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس میں کسی بندے کا ہاتھ نہیں تھا.پھر رَبُّكَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ نشان کس کے لئے ظاہر کیا تھا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مکہ والوں کی بھی خاطر ہو گئی.بے شک خانۂ کعبہ کا بھی اعزاز ہو گیا.مگریہ ایک ضمنی بات تھی.اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ نشان محض تیرے لئے دکھایا تھا اور تو ہی ہمارا اصل مقصود تھا.پس درحقیقت یہ نشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے تھا اور کسی کے لئے نہیں تھا.مکہ کے لوگ بھی اس معجزہ کے تو قائل تھے مگر وہ اس امر کے قائل نہ تھے کہ یہ معجزہ کسی اور کے لئے ظاہر ہوا ہے وہ اتنا تو سمجھتے تھے کہ دعائے ابراہیمی کے پورا ہونے کا یہ ایک ثبوت ہے مگر یہ کہ احترامِ محمدؐ ی میں ایسا ہو اہے اس کو وہ نہیں مانتے تھے.اگر مانتے تو مسلمان کیوں نہ ہو جاتے.اللہ تعالیٰ اسی امر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے احمقو! تم اسے اب بھی نہیں مانتے.حالانکہ ہم نے اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لئے یہ معجزہ دکھا دیا تھا اور جب ہم نے اس کی پیدائش سے بھی پہلے اس کے لئے اپنے معجزات ظاہر کرنے شروع کر دیئے تھے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اب بھی اس کی زندگی کے آخری ایام تک اس کے لئے اپنے نشانات دکھاتے چلے جائیں گے.رَبُّكَ میں رَبّ کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آپؐ کے کام سے اس نشان کا تعلق تھا اگر یہ معجزہ نہ دکھایا جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحیح طور پر نہ ہو سکتی اور نہ صحیح طور پر آپؐکا کام چل سکتا.پس رَبّ کے لفظ نے یہ بھی بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تربیت اور آپؐکے کام کے صحیح
Page 311
طور پر چلنے کے لئے اصحاب الفیل پر تباہی آئی تھی تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس واقعہ کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کو پورا کرنے والے تھے.چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ (البقرۃ:۱۳۰) اے ہمارے رب تو اس نسل میں جسے میں مکہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک نبی بھیجیو.وَابْعَثْ فِيْهِمْ کے معنے ہیں وَابْعَثْ فِیْ اَہْلِ مَکَّۃَ یعنی اے میرے ربّ تو ایک زمانہ میں مکہ کے رہنے والوں میں ایک رسول بھیجیوجو مِنْهُمْ کا مصداق ہو یعنی وہ انہیں میں سے ہو.یہیں کا باشندہ ہو اور انہیں لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں.يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وہ ان اہل مکہ کو تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے.وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ اور ان کو تیری کتاب اور حکمت سکھائے.وَ يُزَكِّيْهِمْ اور ان کو پاک کرے.اس دعا سے ظاہر ہے کہ یہ رسول مکہ میں آنا تھا.مکہ کے لوگوں کی اس نے اصلاح کرنی تھی اور مکہ کے لوگوں کو اس نے ایک بڑی قوم بنانا تھا.بےشک آپؐنے باقی دنیا کی بھی اصلاح کرنی تھی مگر بہرحال ان کا مقام مکہ کے بعد تھا.تزکیہ کے ایک معنے بڑا بنانے اور ترقی دینے کے بھی ہیں.اس لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو ایک بڑی قوم بنانا تھا.اگر خانۂ کعبہ تباہ ہو جاتا تو لازماً مکہ کے لوگ متفرق ہو جاتے اور وہ تلاشِ معاش کے لئے ادھر ادھر پھیل جاتے.مکہ کے لوگ خانۂ کعبہ کی وجہ سے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے جس طرح مجاور قبروں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی قبر کسی بادشاہ کے حکم سے مٹا دی جائے تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ مجاور جو اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جن کی آمد قبر کے چڑھاوے پر منحصر ہوا کرتی ہے وہ بھی ادھر ادھر چلے جائیں گے.اور اپنی معاش کے لئے کوئی اور ذریعہ تلاش کریں گے.اگر خانۂ کعبہ بھی تباہ ہو جاتا تو مکہ کے لوگوں کے لئے گذارہ کی کوئی صورت نہ رہتی اور نہ مکہ والوں کا کوئی ادب اور احترام ان کے دلوں میں باقی رہتا.گویا ٍخانۂ کعبہ کی تباہی کے ساتھ اوّل تو مکہ والوں کا احترام جاتا رہتا.لوگ کہتے کہ مکہ والے یوں ہی دعویٰ کرتے رہتے تھے کہ یہ بڑا مقدس مقام ہے.اگر مقدس مقام ہوتا تو تباہ کیوں ہوتا.پھر لازمی طور پر وہ متفرق ہو کر ادھر ادھر چلے جاتے اور اس طرح آنے والے موعود کے لئے جو جگہ مقرر تھی وہ بھی جاتی رہتی.آخر اگر مکہ اجڑ جاتا تو آنے والا موعود کہاں آتا اور وہ آکر کیا کرتا.اس کے متعلق تو یہ خبر دی گئی تھی کہ وہ مکہ میں آئے گا اور مکہ کے لوگوں میں رہے گا.یہ خبر اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی تھی جب تک مکہ کو آباد نہ رکھا جاتا.پس آنے والے موعود کے ظہور اور اس کے کام کی تکمیل کے لئے ضروری تھا کہ خانۂ کعبہ کو قائم رکھا جاتا اور اسی کی
Page 312
طرف رَبُّکَ میں اشارہ کیا گیا ہے پس رَبُّکَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ خانۂ کعبہ سے بھی زیادہ اصحاب الفیل کی تباہی کا موجب درحقیقت تیرا احترام تھا.اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ میں اصحاب الفیل کے لفظ کے استعمال کرنے میں حکمت ایک اور بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ابرہہ نے بے شک خانۂ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر اس کے لشکر نے یہ ارادہ نہیں کیا تھا.اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چلو اور وہ چل پڑے.مگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے اصحاب الفیل کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا.آخر یہ زیادتی بلاوجہ تو نہیں.اللہ تعالیٰ کے لئے کیا یہ مشکل تھی اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَبْرَھَۃ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے ساتھ کیا کیا.یا کہہ دیتا کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِـمَلِکِ الْیَمَنِ.کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے یمن کے بادشاہ کے ساتھ کیا کیا.وہ ایسا کہہ سکتا تھا مگر خدا نے وہ نہیں کہا جو سیدھی بات تھی بلکہ چکر دے کر یہ کہا ہے کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ اس کے صاف معنے یہ ہیں کہ یہاں کوئی نیا نکتہ بیان کیا گیا ہے اور وہ اسی امر کا اظہار ہے کہ ہم نے صرف ابرہہ کو ہی تباہ نہیں کیا بلکہ ابرہہ کی قوم کو بھی تباہ کر دیا.اصحاب الفیل صرف وہ نہیں تھے جو ابرہہ کے ساتھ تھے بلکہ فیل والی قوم یمن کی حاکم قوم تھی جس کی تباہی کا اس آیت میں ذکر آتا ہے.اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے اگر کسی لشکر کی توپیں توڑ دی جائیں یا کسی بٹالین کو تباہ کردیا جائے توہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے توپوں والوں کو تباہ کر دیا.کیونکہ توپوں والی حکومت یا تو انگریزوں کی ہے یا فرانسیسیوں کی ہے یا امریکنوں کی ہے.ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں بٹالین کو تباہ کر دیا مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے توپوں والوں کو تباہ کر دیا.جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے توپوں والوں کو تباہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ایسی ضرب لگائی کہ صرف وہی لشکر تباہ نہیں ہوا جو لڑنے آیا تھا بلکہ ایسی ضرب لگائی کہ ان کے پیچھے جو ملکی قوت تھی اسے بھی توڑ دیا.اس مثال کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہاں خالی ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی کا ذکر نہیں کیونکہ اصحاب الفیل صرف ابرہہ اور اس کا لشکر نہیں تھا بلکہ اصحاب الفیل وہ قوم تھی جو یمن پر حکومت کر رہی تھی.اللہ تعالیٰ اس ساری قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے ابرہہ کو ہی نہیں مارا بلکہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایسی زک پہنچائی کہ جس کے ساتھ یمن میں نجاشی کی حکومت بھی بالکل فنا ہو گئی.یہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس میں کیا حکمت ہے.بہرحال اصحاب الفیل کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ صرف ابرہہ اور اس کا لشکر تباہ نہیں ہوا بلکہ ان کی وہ پچھلی طاقت جو یمن میں تھی وہ بھی تباہ ہوگئی اور اس تباہی کا اتنا اثر پڑا کہ عیسائیوں کے
Page 313
قویٰ بالکل ڈھیلے ہو گئے.اس تباہی میں اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی حکمت کام کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ ایک بھاری حکومت کے کسی لشکر کا تباہ ہو جانا خطرہ کو کم نہیں کرتا بلکہ اور بھی بڑھا دیتا ہے.اگر کسی چور کو پکڑتے ہوئے کوئی کانسٹیبل مارا جائے تو چوروں کے لئے خطرہ کم نہیں ہو جاتا بلکہ بڑھ جاتا ہے.اسی طرح اگر بعض لوگ بغاوت کر رہے ہوں اور فوج کا کوئی دستہ ان کا مقابلہ کرتا ہوا مارا جائے تو اس دستے کا مارا جانا خطرہ کم نہیں کرتا بلکہ اور بھی بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس کے بعد حکومت اپنی ساری طاقت اس قلعہ کو مٹانے کے لئے صرف کر دیا کرتی ہے.اگر صرف ابرہہ مارا جاتا اگر صرف اتنا اثر ہوتا کہ اس کے لشکر کو نقصان پہنچ جاتا اور وہ شکست کھا کر بھاگ جاتا تو پیچھے یمن کی حکومت موجود تھی، حبشہ کی حکومت موجود تھی،جس کا وہ گورنر تھا اور یہ حکومتیں اپنی ساری طاقتیں عرب کی تباہی میں لگا سکتی تھیں اور اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سخت خطرہ میں پڑجاتی.کیونکہ اگلے سال پھر عیسائی حکومت کا کوئی لشکر مکہ پر حملہ آور ہو جاتا.اس سے اگلے سال پھر کوئی حملہ کر دیتا.یمن میں ان کا اڈہ تو قائم ہی تھا وہ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ اپنے لشکر بھیج کر عربوں کو تباہ کر سکتے تھے.اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں پلنا، مکہ والوں میں چلنا پھرنا، مکہ والوں میں جوان ہونا اور پھر مکہ والوں کا آپؐ کے بلند کیریکٹر کو دیکھنا اور دعائے ابراہیمی کو اس رنگ میں پورا ہوتے دیکھنا کہ مکہ والوں میں سے ہی ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے قطعی طور پر ناممکن ہوجاتا.وہ قوم جسے ایک حکومت کے بھاری لشکروں کا متواتر سامنا کرنا پڑتا اوّل تو وہ پراگندہ ہو جاتی اور پھر اگر پراگندہ نہ بھی ہوتی تب بھی اسے یہ فرصت کہاں مل سکتی تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھے اور آپؐکی زندگی کی ایک ایک حرکت میں آپؐکی صداقت کے آثار مشاہدہ کرے اس طرح اسلام کی تمام بنیاد خطرہ میں پڑ جاتی.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہی نہیں بلکہ اس قوت کو ہی کچل دیا جو اس کے پیچھے کام کر رہی تھی اور ان کو ایسی مار پڑی اور عربوں میں اتنی دلیری پیدا ہو گئی کہ انہوں نے بغاوتیں شروع کر دیں.نتیجہ یہ ہوا کہ ایران نے اس جگہ پر آکر قبضہ کر لیا اور نجاشی کی حکومت جاتی رہی(البدایۃ والنـھایۃ ذکر خروج الملک من الـحبشۃ).چونکہ مکہ والوں سے ایرانی حکومت کا کوئی جھگڑا نہیں تھا.اس لئے وہ چپ کر کے بیٹھ گئی اور جن کو مکہ والوں پر غصہ آسکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑیں تک اکھاڑ کر پھینک دیں.اس کے بعد حبشہ میں بے شک نجاشی کی حکومت قائم رہی مگر یمن میں اس کا جو اڈہ قائم تھا وہ نہ رہا اور چونکہ وہ یمن سے ہی حملہ کر سکتا تھا اور اب یمن پر ایران قابض ہو چکا تھا.اس لئے عرب کو اس کی طرف سے حملہ کا کوئی خطرہ نہ رہا.پس اصحاب الفیل سے نجاشی کی حکومت مراد ہے.ہاتھی عرب میں نہیں ہوتا تھا بلکہ حبشہ سے آتا تھا پس اصحاب الفیل سے مراد بھی حبشہ کی حکومت ہی
Page 314
ہے.اللہ تعالیٰ اس حکومت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے اصحاب الفیل سے کیا کیا اور کس طرح ہم نے حبشہ کی حکومت کو ہی عرب سے مٹا دیا.گویا ہم نے صرف ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہی شکست نہیں دی بلکہ عرب سے حبشہ کی حکومت ہی مٹا دی تاکہ اس کی طرف سے بار بار حملہ کا خطرہ نہ رہے.اصحاب الفیل کے واقعہ کی تفصیل تاریخی لحاظ سے اب میں اصحاب الفیل کا واقعہ تاریخوں کے اس نقطۂ نگاہ کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے بیان کرتا ہوں جو اس کے متعلق میرا ہے.واقعہ اصحاب الفیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں اکثر اور معتبر روایات کے مطابق اور پیدائش سے دس۱۰، پند۱۵رہ، تئیس۲۳، تیس۳۰، چالیس۴۰، پچا۵۰س اور ستر۷۰ سال پہلے مختلف کمزور روایتوں کے مطابق ہوا.سہیلی کے نزدیک پچاس دن قبل از ولادت اور دمیاتی کے نزدیک پچپن دن قبل از ولادت یہ واقعہ ہوا.بعض کے نزدیک چالیس دن پہلے اور بعض کے نزدیک ایک ماہ پہلے ہوا.تفصیل اس واقعہ کی یوں ہے کہ اس واقعہ سے چند سال پہلے یمن پر حمیر کی حکومت تھی (حمیر عرب کی ایک قوم ہے) اور ذونواس حمیری بادشاہ اس علاقہ پر حکومت کر رہا تھا.ذونواس حمیری بادشاہ کے متعلق بعض مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ وہ مذہباً یہودی ہو گیا تھا.اور بعض کے نزدیک وہ یہودی نہیں ہوا تھا بلکہ مشرک تھا.لیکن یہودیوں کی طرف مائل تھا (تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا).غالباً اس کے یہودی ہونے کا خیال اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ وہ عیسائیوں کا دشمن تھا مگر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہودی ہو گیا ہو.بہرحال اس کے دل میں عیسائیوں کی سخت دشمنی تھی.میرا خیال ہے کہ شاید یہ دشمنی اس لئے ہو کہ یمن حبشہ کے ساحل کے مقابل میں ہے.ممکن ہے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا حبشہ سےبگاڑ ہو جایا کرتا ہو.ایک دفعہ اس نے غصہ میں آکر اپنے ملک کے بیس۲۰ ہزار عیسائی گرفتار کئے اور خندقیں کھود کر ان کو زندہ جلا دیا.مفسرین کا خیال ہے کہ سورۃ البروج کی آیات قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ.النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ.اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ.وَّ هُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ.(البروج:۵تا۸) میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے(تفسیر ابن کثیر زیر آیت البروج ۴تا۷).اس نے خندقیں کھود کر آگ جلائی اور بیس۲۰ ہزار عیسائیوں کو اس آگ میں زندہ جلا دیا.صرف ایک شخص جس کا نام دوس ذو ثعلبان تھا وہ بچ کر بھاگ نکلا.اس وقت عیسائیوں کا تمام دارومدار رومی حکومت پر تھا.رومی حکومت کے تمام باشندے عیسائی تھے(اردو دائرہ معارف اسلامیہ زیر لفظ بوذنطیہ) اور پھر یہ حکومت اتنی زبردست اور وسیع تھی کہ اس وقت نصف دنیا پر حکومت کر رہی تھی شام اور فلسطین اور
Page 315
اناطولیہ سب اس کے تابع تھے.اسی طرح مصر اور لیبیا اور حبشہ تک کے بادشاہ اس کے ماتحت تھے.عیسائی لوگ اس وقت بھاگ کر وہیں پناہ لیا کرتے تھے.جیسے پچھلے زمانہ میں ہندوستان کے مسلمان ٹرکی اور بعد میں افغانستان کے بادشاہ کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے مصائب میں اگر کوئی کام آسکتا ہے تو یہی ہیں.عیسائی بھی اس وقت اپنا ملجاء و ماویٰ صرف قیصر روم کو سمجھتے تھے.دوس ذو ثعلبان اس وقت بھاگ کر قیصر کے پاس پہنچا.اس زمانہ میں ایران اور روم کی آپس میں بڑی کثرت سے لڑائیاں ہوتی تھیں(اردو دائرہ معارف اسلامیہ زیر لفظ ساسانیاں) جس کی وجہ سے کئی قیصر سال کا اکثر حصہ شام میں ہی گذارتے تھے.اس وقت بھی قیصر وہیں تھا.اس نے قیصر کے پاس پہنچ کر فریاد کی کہ اس قتل عام کا بدلہ لیا جائے.قیصر روما کی سرحد یمن کے ساتھ نہیں ملتی تھی درمیان میں پانچ چھ سو میل کا ایک آزاد علاقہ تھا اس لئے قیصر روما خود تو کچھ نہیں کرسکتا تھا مگر وہ اتنے عظیم الشان قتل عام کو نظرانداز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے دوس ذوثعلبان کو حبشہ کے بادشاہ کے نام جو اس کے ماتحت تھا ایک چٹھی لکھ کر دی.حبشہ اور یمن کے درمیان بحیرۂ احمر ہے اور اس زمانہ میں دو تین دن میں کشتیاں ادھر سے ادھر چلی جاتی تھیں.آج کل کے جہازوں کے لحاظ سے تو یہ سفر چند گھنٹوں کا ہے.بہرحال اس نے حبشہ کے بادشاہ کے نام چٹھی لکھی کہ اس واقعہ کی طرف توجہ کرو اور جو عیسائی مارے گئے ہیں ان کا بدلہ لو.اس وقت حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے.انگریزی میں ان کو نیگسNEGUS کہتے ہیں.اس وقت جو نجاشی حکومت کر رہا تھا اس کا نام اصحمہ بن بحر تھا.یہ اسی بادشاہ کا نام ہے جس کے زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور جس کے متعلق تاریخ اور احادیث سے ثابت ہے کہ وہ آخری زمانہ میں مسلمان ہو گیا تھا.اسی کی زندگی کا یہ واقعہ ہے (اردو دائرہ معارف اسلامیہ زیر لفظ نجاشی) اور اسی کے نام بادشاہ نے چٹھی لکھی کہ دوس ذو ثعلبان کی مدد کرو.چنانچہ اس نے اپنے دو جرنیل ایک بہت بڑے لشکر کےساتھ یمن بھجوائے.ان میں سے ایک کا نام اریاط تھا اور دوسرے کا نام ابرہہ بن الصباح اور اس کی کنیت ابویکسوم تھی(تفسیر ابن کثیر سورۃ الفیل ).یہ سفید رنگ کا تھا.رومی حکومت اور اس کے ماتحت جو حکومتیں تھیں ان سب میں یہ دستور تھا کہ وہ عام طور پر دو دو جرنیل بھیجا کرتے تھے یہاں تک کہ رومی حکومت میںبعض دفعہ دو ڈکٹیٹر مقرر کئے جاتے تھے.کلیوپٹرا کا باپ جب مرا ہے تو اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو بادشاہت دے دی تھی.یہی کلیوپٹرا ہے جس سے روم کے ایک ڈکٹیٹر نے شادی کی(Encyclopedia Brictanica Under word "Cleopatra") اور وہ اسی قضیہ میں مارا گیا.دراصل وہ دو ڈکٹیٹر یا دو جرنیل اس لئے مقرر کرتے تھے کہ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ اگر صرف ایک شخص مقرر کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بغاوت کرے لیکن
Page 316
اگر دو ہوئے تو ان میں سے ایک دوسرے کا محافظ ہو جائے گا اور اس طرح خرابی پیدا نہیں ہو گی.گو کسی قوم کے دو بادشاہ ہونا ایک بالکل غیرطبعی چیز ہے.مگر ان لوگوں میں عرصہ دراز تک یہ بات قائم رہی.اسی طرح جب وہ کسی جگہ جرنیل بھیجتے تو جرنیل بھی دو دو اکٹھے بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ ایک دوسرے کے نگران رہیں اور کوئی شرارت نہ کر سکیں.میں بتا چکا ہوں کہ جو دو جرنیل یمن بھیجے گئے ان میں سے ایک کا نام اریاط تھا اور دوسرے کا نام ابرہہ بن الصباح.ابرہہ کی کنیت ابویکسوم تھی اور وہ سفید رنگ کا تھا.یاد رکھنا چاہیے کہ حبشہ میں دو قسم کی قومیں بستی ہیں ایک کالے رنگ کی اور ایک سفید رنگ کی.شاہی خاندان سفید رنگ کی نسل میں سے ہے.اصل میں یہ نوبی قوم کے افراد تھے جن کی پرانے زمانہ میں اتنی زبردست حکومت تھی کہ وہ یورپ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی.جنوبی مصر اور سوڈان یہ نوبیا کا علاقہ ہے.نوبیا کی حکومت اصل میں عرب تھی اور یہ عرب کے باشندے ہی تھے (A History of Abyssinia vol p:7-9)جنہوں نے پھیلتے پھیلتے حبشہ میں حکومت قائم کرلی.اسی وجہ سے حبشہ کی زبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ تک عربی ہی کی ڈائے لکٹ DIALECT تھی.چنانچہ قرآن کریم میں بیسیوں الفاظ ایسے ہیں جو حبشی زبان کے ہیں.عرب میں بولی جانے والی عربی کے الفاظ نہیں مگر حبشہ کے ساتھ میل جول اور تعلق رکھنے کی وجہ سے عربوں نے ان الفاظ کو اپنی زبان میں داخل کر لیا.نوبی قوم کے افراد عرب ہونے کی وجہ سے نسبتاً سفید رنگ کے تھے اور ابرہہ کا رنگ بھی سفید تھا.معلوم ہوتاہے وہ بھی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو گا.یہ دونوں جرنیل ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ یمن پر حملہ آور ہوئے انہوں نے حمیری حکومت سے جنگ کی اور اسے شکست دے کر یمن میں مسیحی حبش حکومت قائم کر دی.کچھ عرصہ کے بعد دونوں جرنیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا جیسا کہ طبعی طور پر ان دو افراد میں ہوا کرتا ہے جو ایک جیسی طاقت رکھتے ہوں.اریاط اور ابرہہ میں جب اتفاق نہ ہو سکا تو وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے اور اپنے اپنے ڈویژن لے کر ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراء ہو گئے.یہ ایک اصول ہے کہ جب قوم میں بیداری اور زندگی ہوتی ہے تو اس کے افراد قومی مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں اور جب قوم میں تنزّل آجاتا ہے تو اس کے افراد ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دے دیتے ہیں.ابھی تک حبشیوں میں قومی بیداری موجود تھی چنانچہ جب لشکر ایک دوسرے کے مقابلہ میں صف آراء ہوئے تو دونوں جرنیلوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لڑائی تو ہماری آپس میں ہے ہم قوم کو کیوں مروائیں اگر ہم نے اسی طرح لڑائی کی تو یمن میں سے نجاشی کی حکومت بالکل جاتی رہے گی.چنانچہ لڑائی کو ملتوی کر کے ان
Page 317
دونوں نے آپس میں ملاقات کی اور ان خیالات کا اظہار کیا کہ اس کے نتیجہ میں ہماری قوم کو نقصان پہنچے گا.ہمیں کوئی ایسا طریق اختیار کرنا چاہیے جس سے قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور ہمارے جھگڑے کا بھی فیصلہ ہو جائے چنانچہ ان دونوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑیں جو جیت جائے اور دوسرے کو قتل کر دے وہ حکومت کرے.چنانچہ اس فیصلہ کے مطابق وہ دونوں آپس میں لڑنے کے لئے نکلے.فیصلہ یہ تھا کہ فوج کو ہٹا دیا جائے گا.چنانچہ ایسا ہی ہوا فوج ہٹا دی گئی اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے آگئے اریاط نے چابک دستی سے آگے بڑھ کر ابرہہ پر ایسا کاری وار کیا کہ اس کا ناک، کان اور گلا کٹ گیا لیکن اس وقت اس کا ایک غلام جو اس سے عشق رکھتا تھا بغیر کسی کو بتائے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر یہ تمام نظارہ دیکھ رہا تھا.جب اس نے دیکھا کہ اس کا آقا گر گیا ہے تو اس کی محبت نے جوش مارا اور وہ اپنے آقا کی مدد کے لئے آگے بڑھا.ادھر اریاط ابرہہ کی طرف بڑھا کہ اسے تلوار سے مار ڈالے اور ادھر اچانک پیچھے سے ابرہہ کے غلام نے اریاط پر حملہ کر دیا اور خنجر سے اسے مار ڈالا.اس طرح جو فاتح تھا وہ مر گیا اور مفتوح زندہ رہا.چند دنوں کے بعد ابرہہ کے زخم اچھے ہو گئے اور ساری حکومت اس کے قبضہ میں آگئی اور اس طرح ابرہہ یمن کا واحد بادشاہ بن گیا.جب نجاشی کو یہ خبر پہنچی تو اس پر یہ بات بہت گراں گذری کہ تفرقہ پیدا ہوا اور ایک جرنیل نے دوسرے جرنیل کے خلاف حملہ کیا اور اسے مار دیا.نجاشی فطرتاً بہت شریف آدمی تھا.بلکہ خود ابرہہ کے متعلق تاریخی شہادتوں سے یہ امر ثابت ہے کہ وہ بھی بہت حلیم الطبع تھا اور اس نے مکہ کے خلاف جو کارروائیاں کیں وہ جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا محض پولٹیکل وجوہات کی بنا پر تھیں.بہرحال نجاشی چونکہ شریف بادشاہ تھا اسے یہ خبر ملنے پر بہت رنج ہوا کہ میرے جرنیل آپس میں لڑے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا.چنانچہ اس نے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں مقتول کا انتقام لینے کے لئے ابرہہ کی پیشانی کے بال کھینچوں گا اور اس کے ملک کو اپنے پاؤں تلے روندوں گا.پرانے زمانہ میں یہ طریق رائج تھا کہ جب کسی شخص کو ذلیل کرنا مدّ ِنظر ہوتا تھا تو اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر کھینچا جاتا.نجاشی نے بھی قسم کھائی کہ میں ابرہہ کو ذلیل کرنے کے لئے اس کی پیشانی کے بال مونڈ دوں گا.اور اس کے ملک کو اپنے پاؤں تلے روندوں گا.یہ بھی ایک محاوہ ہے جس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ میں اسے شکست دوں گا.اور اسے دنیا کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا کروں گا.نجاشی نے اپنے دربار میں یہ بات کہی تو ابرہہ کے کسی دوست نے فوراً یہ بات ابرہہ تک پہنچا دی کہ اس طرح بادشاہ نے قسم کھائی ہے کہ میں ابرہہ کی پیشانی کے بال کھینچوں گا اور یمن کا ملک اپنے پاؤں تلے روندوں گا.ایسا معلوم ہوتاہے کہ نجاشی اس واقعہ کی وجہ سے یمن پر حملہ کرے گا اور آپ کو گورنری
Page 318
سے برطرف کر دے گا ابرہہ بہت ہوشیار آدمی تھا جب اسے یہ خبر پہنچی تو اس نے ایک نائی بلوایا اور اپنی پیشانی کے بال منڈوا دیئے اسی طرح ایک بوری لی اور اسے یمن کی مٹی سے بھر دیا.اس کے بعد اس نے یہ دونوں چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ نجاشی کے پاس بھجوا دیں اور ساتھ ہی معافی کا ایک خط لکھا اور معذرت کی کہ ان ان حالات میں یہ واقعہ ہوا ہے.اگر قصور ہے تو ہم دونوں کا مشترکہ ہے لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے کسی دھوکے کے ماتحت نہیں ہوا.ہمارا فیصلہ یہی تھا کہ ہم میں سے جو شخص دوسرے کو مار لے گا وہ یمن کا حاکم بن جائے گا.اگر میںمارا جاتا تو وہ بادشاہ بن جاتا.مگر چونکہ لڑائی میں وہ مارا گیا اس لئے اس فیصلہ کے مطابق میں ہی یمن کا حاکم بنا.اس میں کسی فریب یا دھوکے بازی کا دخل نہیں اور نہ اچانک کسی پر حملہ ہوا ہے بلکہ سوچی سمجھی ہوئی تدبیر اور باہمی فیصلہ کے مطابق ہم نے آپس میں یہ لڑائی کی تھی.اس کے ساتھ ہی اس نے لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ بادشاہ سلامت نے قسم کھائی ہے کہ وہ میری پیشانی کے بال کھینچوائیں گے.میں اس قسم کو پورا کرنے کے لئے اپنی پیشانی کے بال مونڈ کر حضور کی خدمت میں بھجوا رہا ہوں اسی طرح مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ حضور نے قسم کھائی ہے کہ میں یمن کے ملک کو اپنے پاؤں تلے روندوں گا.اس قسم کو پورا کرنے کے لئے میں یمن کی مٹی ایک بوری میں بھر کر بھجوا رہا ہوں.آپ اس کو پاؤں تلے روندیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی.باقی جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں آپ کا مطیع اور فرمانبردار ہوں اور مجھے آپ کی غلامی پر فخر ہے.اس کا یہ طریق کہ اس نے اپنی پیشانی کے بال مونڈ کر بھیج دیئے اور یمن کی مٹی ایک بوری میں بھر کر اس لئے پیش کی کہ بادشاہ اس کو اپنے پاؤں تلے روندے اور اپنی قسم پوری کر لے.نجاشی کو بہت پسند آیا اور اس نے لکھا کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں اور تمہیں اپنی طرف سے یمن کا گورنر مقرر کرتے ہیں.(السیـرۃ النبویۃ لابن ھشام غلب ابرھۃ الاشـرم علی امر الیمن و قتل اریاط) جب ابرہہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اس خوشی میں کہ بادشاہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میری جان بخشی کی ہے فیصلہ کیا کہ میں یمن میں ایک بڑا بھاری گرجا بنواؤں گا.اتنا بڑا کہ جس کی مثال ان علاقوں میں نہ پائی جائے چنانچہ جب بادشاہ کی طرف سے اسے گورنری پر فائز ہونے کے آرڈر ملے اور ساتھ ہی یہ بھی اطلاع آگئی کہ ہم تمہیں معاف کرتے ہیں تو ابرہہ نے بادشاہ کو شکریہ کی ایک چٹھی لکھی جس میں یہ بھی تحریر کیا کہ آپ نے مجھ پر جو یہ مہربانی کی ہے کہ مجھے یمن کا گورنر مقرر کر دیا ہے اور میرے قصور سے درگذر فرمایا ہے میں نے اس خوشی میں آپ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لئے یہ منت مانی ہے کہ میں یمن میں ایک بہت بڑا گرجا بنواؤں گا جس کی مثال اور ممالک میں نہ پائی جائے.چنانچہ اس منت کو پورا کرنے کے لئے اس نے دور دور سے انجینئر بلوائے.اچھی لکڑی، اچھا میٹریل اور اچھے رنگساز مہیا کئے اور
Page 319
ایک بہت بڑا گرجا بنوایا.یہ گرجا اتنا بلند تھا کہ اس کو دیکھتے وقت انسان کی ٹوپی گر جاتی تھی.عربی میں کلاہ کو قلنسوہ کہتے ہیں.چونکہ یہ گرجا ایسا تھا جس کو دیکھتے ہوئے سر پر سے ٹوپی گر جاتی تھی اس لئے عربوں نے اس کا نام قلیس رکھ دیا.یعنی وہ گرجا جس کے دیکھنے سے ٹوپی گر جاتی ہے(عام الفیل وقصۃ ابرھۃ شـرح زرقانی ، قصۃ الفیل).جب گرجا بن گیا تو اس کے بعد اس نے صرف اس گرجا کی تعمیر پر ہی کفایت نہیں کی بلکہ یہ بھی کوشش شروع کر دی کہ عرب خانہ کعبہ کو چھوڑ کر قلیس کا حج کریں اور اسی کو اپنا مرکز اور مرجع قرار دے دیں.(تفسیر ابن کثیر) اصحاب الفیل کے واقعہ کے متعلق ایک خاص مضمون کا انکشاف یہاں وہ مضمون آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں صرف مجھ پر کھولا ہے اور جس کی طرف تیرہ سو سال تک مسلمانوں کی توجہ نہیں گئی.وہ مضمون یہ ہے کہ یہ دو۲ سورتیں یعنی سورۃ الفیل اور سورۂ ایلاف اس حقیقت کا اظہار کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بلکہ آپؐکی پیدائش سے بھی پہلے آپؐکے دشمنوں اور دوستوں کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں یعنی آپؐکی آمد کی انتظار میں اگر ایک طرف آپؐکے دشمنوں نے تیاری شروع کر دی تھی تو دوسری طرف آپؐکے دوستوں نے بھی تیاری شروع کر دی تھی کہتے ہیں ’’ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات‘‘.یعنی ترقی کرنے والے وجود کی طرف شروع میں ہی نظریں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں.یہ تو ایک دنیوی ضرب المثل ہے اللہ تعالیٰ کی بھی ہمیشہ سے یہ سنت چلی آئی ہے کہ جب بھی کوئی مامور آنے والا ہوتاہے اس کی بعثت سے پہلے اس کے متعلق چہ میگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں جو ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ اب وہ زمانہ بالکل قریب آگیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی موعود نے مبعوث ہونا ہے.اگر پرانی باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آسکیں تو اس زمانہ کو ہی دیکھ لو.ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سو سال میں عام طور پر مسیح موعود اور مہدیٔ معہود کے ظہور کے متعلق لوگوں میں احساس پید اہو چکا تھا اور ان میں اس کے متعلق حرکت اور بیداری پائی جاتی تھی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے یہ حرکت پیدا ہوئی اور یہ حرکت کسی ایک قوم میں پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں اور عربوں سب میں یہ احساس تھا کہ کوئی عظیم الشان ظہور ہونےو الا ہے.عرب لوگ قیاس کرتے تھے کہ دعوۃ ابراہیمی والا موعود آنے والا ہے.عیسائی سمجھتے تھے کہ فارقلیط آنے والا ہے یا ’’وہ نبی‘‘ جس کی خبر دی گئی تھی دنیا میں ظاہر ہونےو الا ہے اور یہودی سمجھتے تھے کہ وہ نبی جس نے انہیں غلامی سے آزادی دلانی ہے اور جس نے موسٰی کا مثیل ہونا ہے وہ دنیا میںمبعوث ہونے والا ہے.یہودی صرف موسٰی نبی کے مثیل کی آمد کے قائل تھے اور وہ اس امید میں لگے ہوئے تھے کہ عنقریب وہ مقدس انسان جس کی نوشتوں میں خبر دی گئی تھی مبعوث ہونےو الا ہے مگر یہ پیشگوئیاں تو موسٰی کے زمانہ سے تھیں.موسٰی نے خبر دی تھی کہ ایک
Page 320
زمانہ میں میرا مثیل دنیا میں آئے گا اور وہ آتشی شریعت اپنے ہمراہ لائے گا(استثناء باب ۳۳ آیت ۱،۲).پس یہ امید کوئی نئی امید نہیں تھی بلکہ موسٰی کے زمانہ سے ہی انہیں یہ خبر مل چکی تھی.مگر سوال یہ ہے کہ اس آنے والے موعود کے متعلق ان کے دلوں میں خلش اور تڑپ کیوں نہ داؤد ؑ کے وقت میں پیدا ہوئی؟ کیوں نہ سلیمانؑ کے وقت میں پیدا ہوئی؟ کیوں نہ زکریاؑ کے وقت میں پیدا ہوئی؟ کیوں نہ حزقیل کے وقت میں پیدا ہوئی؟ اس امید کی کسی قدر ابتدا مسیح کے وقت میں ہوئی ہے چنانچہ حضرت مسیحؑ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو کیا سمجھیں کیا آپ مسیح ہیں یا ایلیاہ ہیں یا ’’وہ نبی‘‘ (یوحنا باب ۱ آیت ۱۹تا۲۱) گویا ’’وہ نبی‘‘ کی آمد کا احساس کسی قدر حضرت مسیحؑ کے زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ احساس بہت ہی تیز ہو گیا تھا اور یہ الٰہی سنت اور دستور ہے کہ جب کسی موعود نے آنا ہو تو اس کی آمد سے پہلے ہی طبائع میں ایک عام احساس اس کے متعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کی انگلیاں اس کی طرف اٹھنے لگتی ہیں.پس میں نے اس سورۃ پر جو کچھ غور کیا ہے اس کے لحاظ سے میری تحقیقات یہی ہے کہ اس زمانہ میں لوگوں کےدلوں میں آنے والے موعود کے متعلق ایک جستجو شروع تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ظہور ہونے والا ہے.یہ جستجو عربوں کے دلوں میں بھی تھی کیونکہ حضرت ابراہیمؑ نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ مکہ میں ایک نبی مبعوث ہو گا یہ جستجو یہودیوں کے دلوں میں بھی تھی کیونکہ موسٰی نے یہ کہا تھا کہ میری مانند ایک نبی کھڑا کیا جائے گا.یہ جستجو عیسائیوں کے دلوں میں بھی تھی کیونکہ مسیحؑ نے یہ کہا تھا کہ میرے دوبارہ آنے سے پہلے ایک روح کامل آئے گی جو تمام سچائیوں کو ظاہر کرے گی (یوحنا باب ۱۶ آیت ۱۲،۱۳).پس عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک روح کامل کے ظہور کی امید تھی.عربوں کو یہ امید تھی کہ عرب کا پیغمبر آئے گا اور یہودیوں کو یہ امید تھی کہ موسٰی کا مثیل آنے والا ہے (استثناء باب ۱۸ آیت ۱۸).اور یہ رَو اس قدر چلی کہ ہر قوم بڑے جوش سے اس امید کا اظہار کرتی بلکہ فخر کرتی کہ ہمارا نبی آئے گا تو وہ ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے گا.جیسے اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور انگلستان میں بہت سے ایسے لوگ گذرے ہیں جنہوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا یا اعلان کیا کہ ہم مسیحیت کو غلبہ دینے کے لئے آئے ہیں.اسی طرح مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو مہدویت کے مدعی تھے کیونکہ مسیح اور مہدی کے ظہور کا زمانہ آگیا تھا اور دنیا میں اس کے متعلق ایک عام رَو چل رہی تھی.جس طرح بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اور وہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اب بادل آنے والا اور آسمان سے پانی برسنے والا ہے.اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ماموروں کے آنے سے پہلے زمین میں ایک عام حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور کئی لوگ ماموریت کے مدعی بن جاتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں اور عربوں
Page 321
سب میں یہی رَو جاری تھی عرب اپنی مجالس میں بیٹھتے تو یہی ذکر کرتے کہ اب ابراہیمی وجود ظاہر ہونے والا ہے.یہودی اپنی مجالس میں بیٹھتے تو یہی ذکر کرتے کہ ایسے آثار ظاہر ہورہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موسٰی کا مثیل آنے والا ہے.اسی طرح عیسائی اپنی جگہ باتیں کرتے کہ مسیحؑ کی پیشگوئیاں پوری ہونے والی ہیں.اصل میں تو یہ ایک ہی وجود تھا جس کی آمد کی مختلف قومیں منتظر تھیں مگر وہ سمجھتے یہی تھے کہ ہمارا موعود دوسری اقوام سے بالکل الگ ہوگا.حالانکہ جس کی پیشگوئی ابراہیم ؑ نے کی تھی اسی کی پیشگوئی موسٰی نے کی تھی اور جس کی پیشگوئی موسٰی نے کی تھی اسی کی پیشگوئی ابراہیم ؑ اور عیسٰیؑ نے کی تھی اور جس کی پیشگوئی عیسیٰ ؑ نے کی تھی اسی کی پیشگوئی ابراہیمؑ اور موسٰی نے کی تھی.وجود ایک ہی تھا مگر اپنی اپنی پیشگوئیوں کی وجہ سے ہر قوم کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا نبی آئے گا تو وہ دوسری اقوام کو مارنے کے لئے آئے گا.جب عیسائی سنتے کہ یہودیوں کے دلوں میں بھی امیدیں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی موعود آنے والا ہے جو ان کی قوم کو ترقی دے گا تو وہ اس امید کو تو درست سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کوئی موعود ضرور آنےوالا ہے مگر وہ یہودیوں کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جھوٹے طو رپر ان امیدوں کے سہارے کھڑے ہو رہے ہیں ورنہ وہ موعود جو آنےو الا ہے ہمارا ہے.اسی طرح مکہ والوں میں جب سے یہ احساس پیدا ہوا کہ دعائے ابراہیمی ؑ کے نتیجہ میں عرب میں کوئی پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے تو گو عیسائی یہ تو سمجھتے تھے کہ آنےو الا ضرور آئے گا مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ عرب قوم جو اس موعود کا انتظار کر رہی ہے یہ کوئی پولٹیکل چال ہے.اور وہ ڈرتے تھے کہ اس پولٹیکل چال کے نتیجہ میں کوئی ایسا آدمی عرب میں نہ کھڑا ہوجائے جس کے پیچھے سارا عرب لگ جائے اور اس طرح حکومت کی باگ ڈور اس قوم کے ہاتھ میں آجائے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے اور خود آپؑکے زمانہ میں بھی انگریز اور دوسرے یوروپین جہاں کسی شخص کے متعلق سنتے کہ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو فوراً اس کے پیچھے دوڑ پڑتے حالانکہ انگلستان میں مثال موجود ہے.امریکہ میں مثال موجود ہے کہ وہاں عیسائیوں میں سے بعض لوگوں نے مسیح ہونے یا مسیح کا پیشرو نبی ہونے کا دعویٰ کیا(اردو دائرہ معارف اسلامیہ زیر لفظ مہدی) مگر وہ اس پر برا نہیں مناتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر تو یہ جھوٹا ہے تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے خود بخود تباہ ہوجائے گا اور اگر سچا ہے تو بہرحال اس سے عیسائی دنیا کو فتح ہو گی اور یہ ہمارے فائدہ کی بات ہے.لیکن اگر مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوتا کہ آنے والا موعود ہم میں آنے والا ہے تو وہ سمجھتے کہ یہ کوئی پولٹیکل چال ہے جو عیسائیت کو کمزور کرنے کے لئے اختیار کی جارہی ہے.یہی احساس اس زمانہ کی عیسائیت میں تھا.یہودیوں کے پاس چونکہ حکومت نہیں تھی اس لئے جب وہ سنتے کہ عرب بھی ایک موعود کا انتظار
Page 322
کررہے ہیں جس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عربوں میں سے ہو گا.یا عیسائی بھی ایک موعود کا انتظار کر رہے ہیں.جس کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائیوں میں سے ہو گا.تو وہ اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر بیٹھ جاتے اور اندر ہی اندر پیچ و تاب کھانے لگتے.وہ سمجھتے کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ورنہ ہم ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم ان کے ان خیالات کو برداشت نہیں کر سکتے.اسی طرح عرب بھی جب سنتے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اس موعود کا اپنی اپنی اقوام میں انتظار کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے دلوں پر پتھر رکھ کر بیٹھ جاتے.مگر عیسائیوں میں طاقت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے زور سے اس بات کو مٹا سکتے ہیں.جیسے اس زمانہ میں یوروپین اقوام کی حالت تھی کہ جب کوئی مسیحیت کا مدعی کھڑا ہوتا تو مسلمان تو اسے مار نہیں سکتے تھے حالانکہ مسلمان بھی اس کو اپنا رقیب سمجھتے تھے.مگر جب عیسائی مسلمانوں میں سے کسی کو مہدویت کا مدعی پاتے تو فوراً اس کو مارنے کے لئے کھڑے ہو جاتے.اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب عیسائی دیکھتے کہ عربوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آنے والا موعود عرب ہو گا اور یہودیوں میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ آنےو الا موعود یہود میں سے ہو گا تو وہ رقابت کے احساس کے ماتحت مقابلہ کے لئے کھڑے ہو جاتے اور سمجھتے کہ یہ عیسائیت کو کمزور کرنے کی مخفی تدابیر اختیار کی جارہی ہیں انہی حالات کو دیکھ کر ابرہہ کو محسوس ہوا کہ عرب میں خانۂ کعبہ ایک ایسا مقام ہے جس کی وجہ سے سارا عرب اکٹھا ہو سکتا ہے.ادھر وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ عربوں میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے بلند ہونےاور دنیا میں ترقی کرنے کا وقت آگیا ہے اور ابراہیمؑ کا موعود اب بہت جلد آنے والا ہے اور گو عیسائی ایسے مدعی کو جھوٹا ہی سمجھتے مگر بہرحال ان کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر جھوٹے طور پر بھی ان میں کوئی مدعی کھڑا ہوگیا تو بات خطرناک ہو جائے گی.پہلے ہی ایک جتھہ بنانے کا ذریعہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے یعنی سارے عرب خانۂ کعبہ کو مانتے ہیں اور اس کی عزت و تکریم کرتے اور اسے مقدس مقام تسلیم کرتے ہیں.اگر وہ موعود بھی آگیا تو خانۂ کعبہ تو پہلے ہی ان کے اتحاد کا ذریعہ ہے اس موعود کے ذریعہ یہ اور بھی متحد ہو جائیں گے اور عرب میں سے عیسائی حکومت تباہ ہو جائے گی.عرب میں عیسائیت کی حکومت ایک تو یمن میں تھی اور ایک مدینہ سے اوپر تھی یعنی شمالی عرب کا بہت سا حصہ روم کے بادشاہ نے فتح کیا ہوا تھا اور وہاں اس کی حکومت قائم تھی.گویا فلسطین سے لے کر مدینہ سے ڈیڑھ دو سو میل اوپر تک تمام علاقہ عیسائی حکومتوں کے پاس تھا(المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام الفصل ۳۳ ساسانیوں و بیزنطیوں) اور یہی عرب کے متمدن علاقے تھے یا یمن متمدن علاقہ تھا جس میں غلّہ بھی پایا جاتا تھا، معادن بھی پائے جاتے تھے، اس کی تجارت بھی بڑی بھاری تھی اور یا شمالی علاقے متمدن تھے.ان کی ایران کے ساتھ بھی تجارتیں تھیں اور روم کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات تھے.
Page 323
ان تمام متمدن علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور درمیان کے علاقہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا.جب عربوں میں ایک آنے والے موعود کے متعلق احساسات پیدا ہوئے اور ان میں بیداری کے آثار نظر آنے لگے تو عیسائیوں نے سمجھا کہ اگر عرب منظم ہو گئے تو وہ ہمیں یمن سے بھی نکال دیں گے اور شمالی علاقوں سے بھی نکال دیں گے.معلوم ہوتا ہے جب ابرہہ نے یمن میں گرجا بنایا تو اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہو گیا کہ میں اس گرجا سے یہ بھی کام لوں کہ عرب کے خانۂ کعبہ کی عزت کو گرادوں اور اہلِ عرب کی توجہ اپنے گرجا کی طرف پھرا دوں.اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ عیسائیت پھیلے گی.دوسرے عربوں کا اتحاد ٹوٹ جائے گا.کوئی ایک گھر نہیں رہے گا جس میں وہ جمع ہو سکیں اس لئے آئندہ اگر عرب میں کوئی مدعی کھڑا بھی ہوا تو اس کے لئے اپنی حکومت بنانے میں آسانی نہیں ہو گی.اس خیال کی وجہ سے ابرہہ نے یہ تدبیر کی ورنہ گرجے دنیا میں بنا ہی کرتے ہیں مگر کبھی کسی گرجا سے اس رنگ میں کام نہیں لیا گیا.تاریخ سے ثابت ہے کہ ابرہہ نے اس امر کا اعلان تمام مملکت میں کروا دیا کہ عرب آئندہ قلیس کی زیارت کے لئے آیا کریں اور پھر اپنی اس سکیم کو پوراکرنے کے لئے ابرہہ نے عرب کے بڑے بڑے رؤوسا کو بلا کر انہیں رشوتیں دیں.انعام و اکرام کے وعدے کئے اور ان سے کہا کہ تم سارے عرب میں یہ اعلان کرو کہ آئندہ خانۂ کعبہ کی بجائے اہل عرب اس گرجا میں اکٹھے ہوا کریں جو صنعاء میں بنایا گیا ہے اور بیت اللہ کی بجائے اس کی زیارت کے لئے آیا کریں.ابرہہ کی یہ تحریک صاف بتاتی ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا محض ایک پولٹیکل چال کے طور پر کیا گیا.ورنہ دنیا میں اور ہزاروں گرجے تھے کسی اور گرجے کے متعلق ایسی تحریک کیوں نہیں کی گئی.پھر جو یمن میں گرجا بنایا گیا تھا اس کی یمن کے لحاظ سے بے شک بڑی حیثیت تھی مگر ایبے سینیا کے گرجوں کے مقابلہ میں اس کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی جس کی طرف سے وہ خود ایک گورنر اور تابع حاکم تھا.یقیناً ایبے سینیا میں اس سے بھی بڑے بڑے گرجے ہوں گے.مگر کبھی ایبے سینیا کی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ عرب ان کے گرجوں کی طرف رجوع کریں اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں اسی طرح رومن حکومت میں ہزاروں گرجے تھے اور رومن حکومت اس زمانہ میں ایسی زبردست تھی کہ حبشہ کی بھی وہی حاکم تھی.یمن کی بھی وہی حاکم تھی.پھر شام، فلسطین، انطاکیہ اور یونان وغیرہ سب اس کے قبضہ میں تھے.اتنی بڑی حکومت میں جس قدر گرجے ہو سکتے ہیں اور جتنے شاندار ہو سکتے ہیں وہ ایک ظاہر امر ہے.مگر رومن حکومت نے بھی کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ غیرقومیں ان کے کسی معبد کو مقدس قرار دیں اور اس کی زیارت کے لئے آیا کریں.پھر یمن میں ابرہہ نے ایسا کیوں کیا صرف اس لئے کہ وہ خانۂ کعبہ کی حرمت کو گرا دے.اور خانۂ کعبہ کی حرمت کو گرانے کا خیال اسے اس لئے آیا کہ اس نے دیکھا کہ اہلِ عرب میں یہ احساس پیدا
Page 324
ہو رہا ہے کہ ہم میں ایک نبی آنے والا ہے.اس نے سمجھا کہ اگر یہ دو چیزیں مل گئیں تو لازماً عرب حکومت قائم ہوجائے گی اور ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا چنانچہ اسی احساس کے ماتحت اس نے یہ اعلان کر دیا.بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ نے علاوہ اپنی مملکت میں اس قسم کا اعلان کرنے کے خود نجاشی کو بھی اطلاع دے دی کہ میں چاہتا ہوں کہ عربوں کی توجہ خانۂ کعبہ سےہٹا کر صنعاء کے گرجاکی طرف پھرا دوں اور عربوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ ابرہہ نے نجاشی کو ایسا خط لکھا ہے.جہاں تک میرا احساس ہے میں سمجھتا ہوں کہ نجاشی کو ابرہہ کی اس سکیم سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور غالباً ابرہہ نے اسے اپنی ساری سکیم بتائی بھی نہیں صرف مجملاً اس نے نجاشی کو اطلاع دے دی.جس سے غرض یہ تھی کہ اگر اس سے بعد میں کوئی فتنہ اٹھے تو بادشاہ ناراض نہ ہو کہ مجھے اس سکیم سے کیوں ناواقف رکھا گیا ہے.چنانچہ اس نے اتنی خبر تو دے دی کہ عیسائیت کو یہاں کے لوگوں میں رُوشناس کرنے کے لئے میں عربوں میں یہ تحریک کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صنعاء کے گرجا کی طرف توجہ کریںاور بیت اللہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیں مگر اس نے تفصیلاً اپنی سکیم نجاشی کے سامنے نہیں رکھی.جب عربوں کو معلوم ہوا کہ ابرہہ نے نجاشی کو ایسا خط لکھا ہے اور اس نے اپنی مملکت میں اعلان کرایا کہ آئندہ لوگ خانۂ کعبہ کی بجائے قلیس کی زیارت کے لئے آیا کریں تو ان میں سخت جوش پیدا ہو گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بات معمولی نہیں.یوں گرجے دنیا میں بنا ہی کرتے ہیں.بے شک اس کے پاس روپیہ زیادہ تھا اس لئے اس نے زیادہ بلند عمارت بنا لی یا زیادہ اچھی لکڑی اس نے لگا لی یا زیادہ ماہر انجینئر اس نے گرجا کی تعمیر کے لئے منگوا لئے یا زیادہ پائیدار روغن اس نے کروا دیا مگر یہ کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد بادشاہ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ گرجا سارے عرب کا نقطۂ مرکزی بن جائے.اس کے صاف معنے یہ ہیں کہ یہ ایک پولٹیکل چال چلی جارہی ہے.چنانچہ اس کے نتیجہ میں اہل عرب میں جو سیاسی دماغ کے مالک تھے ان میں بھی قدرتاً جوش پیدا ہوا اور جو مذہبی لوگ تھے ان میں بھی جوش پیدا ہوا اور سب میں یہ احساس پیدا ہوا کہ خانۂ کعبہ کی ہتک کی جارہی ہے خصوصاً قریش میں یہ جوش بہت زیادہ پھیل گیا.جس وقت یہ خبر لوگوں میں عام طور پر پھیل گئی تو ایک دن کوئی عرب جو کوئی مشہور آدمی نہیں تھا بلکہ ایک معمولی آدمی تھا یا زیادہ سے زیادہ کسی قبیلہ کا رئیس ہو گا صنعاء میں آیا (عرب لوگ وہاں آتے رہتے تھے کیونکہ یمن کی بادشاہت منظّم تھی اور انہیں اپنی حاجات لے کر وہاں آنا پڑتا تھا) اور کسی بہانے سے اس نے گرجا میں سونے کی اجازت حاصل کر لی.یوروپین گرجوں کےساتھ تو رہائشی کمرے نہیں ہوتے.مگر ایشیائی گرجوں کےساتھ رہائشی کمرے بھی ہوتے ہیں اور اسی قسم کے کمرے قلیس کے ساتھ بھی تھے.رات کو وہ وہاں سویا تو جیسے اوباش لوگوںکا طریق
Page 325
ہوتا ہے اسے ایک حرکت سوجھی جو اچھی نہ تھی.مگربہرحال جو کچھ ہوا خدا تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت ہوا.اس نے گرجا میں عین عبادت گاہ کے اندر جا کر پاخانہ کر دیا اور پھر کہیں ادھر ادھر بھاگ گیا.اس بارہ میں ابن جریر کی روایت ابن اسحاق سے یہ ہے کہ جب ابرہہ نے نجاشی کو اپنے اس ارادہ سے اطلاع دی کہ وہ نئے گرجا کو سارے عرب کا مرجع بنانا چاہتا ہے اور اس وقت تک دم نہ لے گا جب تک ایسا نہ کر لے اور اس کا چرچا عربوں میں ہوا تو بنو مالک کی شاخ بنو فقیم کے ایک قبیلہ نساء کے ایک شخص کو غصہ آیا اور وہ صنعاء گیا اور اس نے قلیس گرجا میں پاخانہ کر دیا.صبح جب نوکر صفائی کرنے کے لئے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ عبادت گاہ میں پاخانہ پھرا ہوا ہے.اس نے افسروں کو اطلاع دی اور افسروں نے گورنر کو لکھا کہ اس اس طرح ہمارے مقدس مقام میں کوئی شخص پاخانہ پھر گیا ہے اور غالباً پاخانہ پھرنے والا عرب تھا کیونکہ اسی نے رات کو یہاں سونے کی ہم سے اجازت طلب کی تھی اور اب صبح سے وہ غائب ہے.اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قریش کا کام ہے جن کو اس بات پر غصہ ہے کہ ان کی عبادت گاہ کے مقابل پر آپ نے یہ عبادت گاہ بنائی ہے.ابرہہ کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو اسے سخت طیش آیا اور اس کے دل میں مکہ کے خلاف غصہ پیدا ہوا.بعض کہتے ہیں کہ اس نے اسی وقت قسم کھائی کہ وہ مکہ پر چڑھائی کرے گا اور خانۂ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ الگ کر دے گا(الجامع البیان وابن کثیر زیر آیت ھذا).اس کے بعد بعض اور واقعات بھی ہوئے جو ابرہہ کے دل میں متواتر یہ احساس پیدا کرتے چلے گئے کہ خانۂ کعبہ کی موجودگی میں صنعاء کا گرجا کبھی ترقی نہیں کر سکتا.اس بارہ میں دوسری روایت مقاتل بن سلیمان کی ہے.وہ روایت کرتے ہیں کہ قریش کے کچھ نوجوان صنعاء گئے جہاں یہ گرجا تھا اور وہاں کسی کام کے لئے آگ جلائی.اتفاقاً اس دن ہوا تیز چل رہی تھی آگ کی کچھ چنگاریاں اصل عمارت کی طرف اڑ کر پہنچ گئیں اور اس میں آناً فاناً آگ لگ گئی.ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس گرجا میں لکڑی کا کام زیادہ تھا.اس کے علاوہ تاریخ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس گرجا پر روغن کا بہت زیادہ کام کیا گیا تھا چونکہ روغن کو آگ بہت جلدی لگ جاتی ہے اس لئے ممکن ہے اس آگ میں زیادہ تر اس روغن کا بھی دخل ہو جو اس پر کیا گیا تھا(روح البیان).بہرحال یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پیدا ہوئی اور اس گرجے کا ایک حصہ جل گیا.بعض روایات میں تو یہ آتا ہے کہ سارا جل گیا.مگر بعض دوسری روایات میں ذکر آتا ہے کہ سارا گرجا نہیں جلا بلکہ اس کا صرف ایک حصہ جلا(تفسیر ابن کثیر و تفسیر بغوی زیر آیت ھذا).اس پر ابرہہ کے دل میں اور بھی احساس پیدا ہوا کہ جب تک خانۂ کعبہ موجود ہے اس گرجا کی عظمت اہل عرب کے دلوں میں قائم نہیں ہو سکتی.اتفاق ایسا ہوا کہ یہ لوگ جن کی وجہ سے گرجا میں آگ لگی، یہ بھی عرب تھے اور گرجا میں پاخانہ پھرنے والا بھی عرب ہی تھا.یہ ہم نہیں
Page 326
کہہ سکتے کہ انہوں نے عمداً یا ارادتاً گرجا کو نقصان پہنچانے کے لئے آگ جلائی تھی.تاریخ سے صاف ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی کسی غرض کے لئے آگ جلائی تھی مگر اتفاقاً اس روز ہوا تیز چل رہی تھی آگ کی چنگاریاں اڑ کر اصل عمارت تک بھی جا پہنچیں اور انہوں نے گرجا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا.بہرحال یہ ایک اتفاق تھا اور ایسے اتفاقات دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں.یہ تو نہیں ہوتا کہ ہوا سے پہلے کوئی عہد لے لیتا ہے کہ جب میں آگ جلاؤں تو تُو بھی چل پڑیو.مگر چونکہ پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا بادشاہ کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یہ جو کچھ ہو اہے شرارتاً ہو اہے اور اس کے دل میں مکہ کا بُغض اور بھی ترقی کر گیا.اس وقت ابرہہ نے اپنے آدمی بھیج کر عرب کے بعض اچھے اچھے رؤوسا کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ بغیر چڑھائی کرنے کے عربوں کو خانۂ کعبہ کی طرف سے ہٹا کر قلیس کی طرف مائل کیا جا سکے.چنانچہ محمد بن خزاعی اور قیس بن خزاعی جو قبیلۂ خزاعہ کے بڑے سردار تھے ابرہہ کے پاس آئے ابرہہ نے ان سے انعام و اکرام کے وعدے کئے اور ان سے کہا کہ تم عرب میں پھرو اور لوگوں کو توجہ دلاؤ کہ وہ اپنا مرکزی نقطہ صنعاء کے گرجا کو بنا لیں اور خانۂ کعبہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیں(الجامع البیان زیرآیت ھذا).حج کے لئے بھی آئندہ قلیس ہی آیا کریں یہ لوگ عیسائی نہیں تھے مگر جیسے انگریزوں کے زمانۂ اقتدار میں کئی مسلمان ان کی خوشامدیں کرتے پھرتے تھے.یا جہاں بھی کوئی حاکم ہو وہاں بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں جو لالچ میں آجاتے ہیں اور حکام کی خوشامدیں کرتے رہتے ہیں.اسی طرح ان کو بھی جب انعام و اکرام کے وعدے دیئے گئے تو یہ اس دورہ کے لئے تیار ہو گئے چنانچہ بادشاہ سے ہدایتیں لے کر انہوں نے سیدھا رخ مکہ کی طرف کیا.یہ شمال کی طرف نکل گئے.ان کا طریق یہ تھا کہ تمام لوگوں کو جمع کرتے اور پھر انہیں نصیحت کرتے کہ خانۂ کعبہ کو چھوڑو اور صنعاء کے گرجا کی طرف جایا کرو.اگر ایسا کرو گے تو حاکم قوم سے تمہارے تعلقات ہو جائیں گے اور تم بہت جلد ترقی کر جاؤ گے.جس وقت یہ دورہ کرتے ہوئے بنوکنانہ کے علاقہ میں پہنچے اور اہل تہامہ یعنی مکہ اور اس کے نواحی میں رہنے والوں کو اطلاع ہوئی کہ دو عرب سردار ابرہہ نے اس پراپیگنڈا کے لئے بھجوائے ہیں کہ اہل عرب خانۂ کعبہ کو چھوڑ دیں اور صنعاء کے گرجا کو اپنا مرکز بنائیں تو انہوں نے ہذیل قبیلہ کے سردار عروہ بن حیاض کو بلوایا اور اسے کہا کہ تم جاؤ اور صحیح صحیح حالات معلوم کر کے آؤ.آیا واقعہ میں خزاعہ قبیلہ کے سردار محمد بن خزاعی اور قیس بن خزاعی بادشاہ کے کہنے پر اس قسم کا پراپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ خانۂ کعبہ کو چھوڑو اور صنعاء کو اپنا مرکز بناؤ.وہ لوگ بے شک مشرک تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انہیں خانۂ کعبہ سے عقیدت تھی.پھر عقیدت کے علاوہ مکہ کی ساری آمدن ہی خانۂ کعبہ پر تھی اگر خانۂ کعبہ کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی تو صرف ان کے مذہبی احساسات
Page 327
کو ہی صدمہ نہ پہنچتا بلکہ ان کی سیاسی برتری کو بھی سخت صدمہ پہنچتا.پس انہوں نے چاہا کہ ہم پہلے جلدی سے اس کا پتہ لے لیں تاکہ اگر واقعہ میں محمد بن خزاعی ایسا کر رہا ہو تو ہم عرب سردار مل کر اسے اس کام سے روکیں.چنانچہ ہذیل کا سردار عروہ بن حیاض سفر کرتے کرتے وہاں پہنچا اور اس نے دیکھا کہ واقعہ میں محمد بن خزاعی خانۂ کعبہ کے خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے.اس نے سمجھا کہ میں نے اب قوم سے کیا مشورہ کرنا ہے جھٹ کمان سنبھالی تیر رکھا اور ایسا نشانہ لگایا کہ محمد بن خزاعی کے سینہ میں وہ تیر لگا اور وہ اسی وقت مر گیا.یہ دیکھ کر اس کا بھائی قیس بن خزاعی وہاں سے بھاگا اور اس نے ابرہہ کو خبر دی کہ آپ کا ایلچی محمد بن خزاعی جو تمام علاقہ کا دورہ کرتا پھرتا تھا اس کو مکہ والوں نے مار ڈالا ہے(الجامع البیان زیر آیت ھذا) (یہ سوچنے والی بات ہے کہ عربوں میں عام خیال تھا کہ محمد نامی شخص سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں کیا ابرہہ نے محمد بن خزاعی کو اسی نام کی روایت کی وجہ سے ہی تو نہ چنا تھا کہ لوگ اس کے منہ سے یہ تحریک سن کر اس مشہور روایت کی بنا پر سمجھیں گے کہ شاید یہی وہ شخص ہے اور یہی وہ تحریک ہے جس سے عرب کی امیدیں وابستہ تھیں) اب یہ ایک اور واقعہ پیش آگیا جس پر ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے سمجھا کہ جب تک خانۂ کعبہ موجود ہے میرا گرجا لوگوں میں کبھی مقبول نہیں ہو سکتا.ابن حاتم اور حلیۂ ابونعیم میں ایک اور روایت بھی بیان کی گئی ہے مگر میرے نزدیک وہ ایسی قابل اعتبار نہیں.اس میں لکھا ہے کہ کلسوم ابن الصباح حمیری جو ابرہہ کی بیٹی کا بیٹا تھا حج کے لئے گیا.اس جگہ میں ضمنی طور پر یہ بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس روایت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ابرہہ نے اپنی بیٹی یمن کے پرانے شاہی خاندان میں سے ایک شخص کے ساتھ بیاہ دی تھی.یہ وہی خاندان ہے جس کو شکست دے کر ابرہہ اور اریاط نے یمن میں عیسائی حکومت قائم کی.بہرحال کلسوم ابن الصباح حمیری جو ابرہہ کی بیٹی کا بیٹا تھا حج کے لئے گیا.راستہ میں اسے عربوں نے لوٹ لیا.اس روایت پر مجھے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ عیسائی اپنی بیٹیاں غیرعیسائیوں کو نہیں دیتے تھے.اگر کہا جائے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہی تھا تو اس کا حج کے لئے جانا بے معنی ہو جاتا ہے اور اگر وہ عیسائی نہیں ہوا تھا تو کوئی عیسائی اپنی بیٹی کسی غیر عیسائی کو نہیں دیتا تھا خصوصاً جو بڑے خاندان تھے وہ اس بارہ میں بہت احتیاط سے کام لیا کرتے تھے.پس یہ روایت اپنی اندرونی شہادت کے لحاظ سے ہی اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے.بہرحال روایت بتاتی ہے کہ راستہ میں عربوں نے اسے لوٹ لیا اور جس گرجا میں وہ ٹھہرا ہوا تھا اسے بھی لوٹ لیا.اس پر ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا.یہ روایت میرے خیال میں عیسائی اثر کے ماتحت خود بنائی گئی ہے کیونکہ پیچھے جس قدر روایتیں گذر چکی ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جو ابرہہ کو مکہ پر حملہ کرنے کا پولٹیکل حق دیتی ہو.لیکن یہ روایت ایسی ہے جو اس کو حملہ کا پولٹیکل حق دے دیتی ہے.اگر اس کا نواسہ
Page 328
مارا گیا تھا تو یقیناً اسے پولٹیکل حق پہنچ جاتا تھا کہ وہ اس ملک پر حملہ کر دے جس کی طرف سے ایسا فعل ہو اہے.پس میرے نزدیک عیسائی اثر کے ماتحت ابرہہ کے حملہ کو حق بجانب ثابت کرنے کےلئے یہ روایت وضع کی گئی ہے.چونکہ مکہ پر ابرہہ کے حملہ کی کوئی جائز اور معقول وجہ نہیں تھی اور عیسائیوں پر اس سے بہت بڑا الزام آتا تھا.اس لئے ابرہہ کو اس اعتراض کی زد سے بچانے کے لئے یہ روایت گھڑی گئی ہے تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالا جا سکے کہ یہ حملہ بلاوجہ نہیں تھا بلکہ اسے ایک سیاسی اشتعال دلایا گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے عرب پر حملہ کیا اور اس حملہ کا پولٹیکل نقطۂ نگاہ سے وہ پوری طرح حق دار تھا.دوسرے اس روایت کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے اس لئے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابرہہ کی بیٹی کا بیٹا حمیری تھا.تاریخوں سے ثابت ہے کہ ابرہہ کا یمن سے کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا.نجاشی کی طرف سے وہ اس علاقہ کو فتح کرنے کے لئے جرنیل مقرر ہوا تھا.اس لئے بہرحال یمن میں وہ ایک نو وارد کی حیثیت رکھتا تھا.پس اگر اس نے اپنی لڑکی یمن میں بیاہی تھی تو یمن میں آنے کے بعد بیاہی تھی.پھر اس بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑی عمر کا ہو کر حج کے لئے گیا اور یہ واقعہ پیش آیا.ہم اندازاً یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ لڑکا حج کے لئے گیا ہو گا تو وہ بیس بائیس سال کا ضرور ہو گا.پھر یہ تو نہیں کہ یمن میں آتے ہی اس نے سارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا.لازماً اسے حمیر کو شکست دینے اور یمن پر قبضہ پانے میں کچھ سال لگے ہوں گے.پھر اس کے بعد یہ بھی ثابت ہے کہ اریاط اور ابرہہ دونوں میں اختلاف پیدا ہوا اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے ایک لڑائی کی شکل اختیار کر گیا.جس میں اریاط مارا گیا اور ابرہہ یمن کا اکیلا بادشاہ بن گیا.ان تمام جھگڑوں میں اندازاً دو تین سال ضرور صرف ہو گئے ہوں گے.اس کے بعد ایک دو سال اسے اپنی لڑکی کے لئے داماد تلاش کرنے میں صرف ہو گئے ہوں گے.آخر غیرملکی شخص کو یوں ہی آسانی سے تو داماد نہیں بنا لیا جاتا اس شادی کے بعد اس کی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو بائیس سال کی عمر میں حج کے لئے گیا.اگر حمیر کو شکست دینے اور ملکی حالات کو سازگار بنانے میں کم از کم تین سال بھی صرف ہوئے ہوں اور صرف ایک سال غیرملکی داماد تلاش کرنے میں لگا ہو اور یہ سمجھا جائے کہ اس کی بیٹی کا بیٹا ۲۲ سال کی عمر میں حج کے لئے گیا تھا تو یہ ۲۶ سال بن جاتے ہیں گویا یمن میں آنے کے ۲۶ سال بعد ابرہہ نے خانۂ کعبہ پر حملہ کرنے کی سکیم بنائی.ادھر تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نجاشی کے وقت کا یہ واقعہ ہے وہ وہی تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اسلام لایا اور اسلام پر ہی اس نے وفات پائی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے چالیس سال بعد دعویٔ نبوت فرمایا تھا(بخاری کتاب المناقب باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ) اور دعویٔ نبوت کے پانچ سال
Page 329
بعد ہجرت حبشہ ہوئی.گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ۴۵سال کے تھے تب مسلمان حبشہ پہنچے اس کے بعد مزید آٹھ سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے مگر نجاشی ایمان نہیں لایا.۴۵ میں آٹھ۸ جمع کئے جائیں تو ترپن۵۳ سال بن جاتے ہیں.اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور آٹھویں سال آپؐ نے مختلف بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے جن میں سے ایک خط نجاشی کے نام تھا.ترپن۵۳ میں یہ آٹھ۸ سال جمع کئے جائیں تو اکسٹھ۶۱ ہو گئے.گویا اکسٹھ۶۱ سال کی عمر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا اور وہ مسلمان ہو گیا.اسلام لانے کے چھ ماہ بعد نجاشی کا انتقال ہو گیا (شرح زرقانی).اس اکسٹھ۶۱ سال میں وہ چھبیس۲۶ سال جمع کرو جو ابرہہ کے یمن میں گذرے تو ۸۷سال بن جاتے ہیں.پھر اس میں نجاشی کی حکومت کا وہ زمانہ شامل کرو جو اس سے پہلے گذر چکا تھا اور پھر نجاشی کی بادشاہت سے پہلی عمر کا اندازہ لگاؤ تو اندازاً پچیس۲۵ تیس۳۰ سال شمار کرنے پڑیں گے.۸۷میں ۲۵ جمع کئے جائیں تو ۱۱۲ سال بن جاتے ہیں اور اگر تیس۳۰ سال جمع کئے جائیں تو ۱۱۷ سال نجاشی کی عمر بن جاتی ہے اور یہ عمر بالکل غیر طبعی ہے.جب تک تاریخوں سے قطعی طو رپر یہ عمر ثابت نہ ہو اس وقت تک عقل اس امر کو مان نہیں سکتی.پس یہ روایت درایت اور عقل کے اعتبار سے بالکل غلط ثابت ہوتی ہے.اس لئے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں کی طرف سے یہ روایت بعد میں بنائی گئی ہے جسے مسلمان مفسرین نے سادگی سے اپنی تفسیروں میں درج کر لیا.جیسا کہ ان کا عام طریق تھا کہ جو بھی روایت انہیں اپنے کسی راوی کی طرف سے ملتی اسے بغیر تحقیق کئے تفسیر میں درج کر لیتے.اس روایت کی بھی انہوں نے تحقیق نہیں کی.جب بعض عیسائیوں نے یہ روایت بنا کر کسی معتبر نظر آنے والے انسان کے ذریعہ مسلمانوں تک پہنچائی تو مفسرین نے اپنی کتابوں میں درج کر لی.انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ درحقیقت اس روایت کے ذریعہ ابرہہ کے لئے بہانہ تلاش کیا گیا ہے اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کا خانۂ کعبہ پر حملہ ناجائز نہیں تھابلکہ پولٹیکل وجوہ رکھتا تھا.ان روایات میں سے قلیس میں پاخانہ کرنے کی روایت زیادہ معتبر کتب کی ہے اور کثرت سے ملتی ہے گرجا کے جل جانے کی روایت اس سے کم معروف ہے اور کلسوم بن صباح کے حج کی روایت اور بھی کم ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے.پس یہ روایت جو میرے نزدیک خود عیسائیوں نے وضع کی ہے بظاہر واقعات کے خلاف ہے.اور پہلی دو۲ روایتوں میں سے ایک یا دونوں صحیح ہیں.بہرحال ان دونوں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کام ایک فرد کا تھا یا پھر اتفاقی طور پر گرجا کی ہتک ہوئی.دوسرے ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابرہہ نے اپنا یہ مشن بنا لیا تھا کہ خانۂ کعبہ کو کمزور کر دے.اور عرب کو کسی نہ کسی طرح اس کی طرف رجوع کرنے سے روک دے.پس سوال
Page 330
گرجا بنانے کا نہ تھا بلکہ ایک ایسا گرجا بنانے کا تھا جوخانہ کعبہ کو دنیا کی نظروں سے گرا دے اور یہ ایک سوچی سمجھی ہوئی تدبیر مقامِ ابراہیمؑ کو مٹانے کی تھی یا دوسرے لفظوں میں موعودِ کعبہ کی بعثت کو مشکوک و مشتبہ کرنے کی تدبیر تھی.اور گو یہ مضمون ابرہہ کے ذہن میں نہیں ہو سکتاتھا.مگر نتیجہ یہی نکلتا تھا.پس اس واقعہ کو تَرٰی اور رَبُّکَ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلانا کہ یہ واقعہ تیرے احترام اور اعزاز میں ظاہر کیا گیا ہے بالکل درست اور صحیح ہے اور حقیقت یہی ہے کہ درحقیقت اس واقعہ کے بیان سے خانۂ کعبہ کے اعزاز سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے اعزاز کا بیان کرنا مقصود ہے.بہرحال ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اور اپنے ساتھ کچھ ہاتھی بھی لے لئے، ایک ہاتھی کا نام محمود تھا بعض روایات میں ہے کہ اس کے ساتھ آٹھ ہاتھی تھے بعض میں ہے کہ بارہ تھے.بعض میں ہے کہ نجاشی نے محمود نامی ہاتھی اس غرض سے بھجوایا تھا مگر یہ درست نہیں معلوم ہوتا کیونکہ نجاشی کا طریق اس کے خلاف ہے دوسرے کہیں تاریخ میں ذکر نہیں کہ نجاشی کو اس واقعہ کی اطلاع دی گئی تھی.بہرحال یہ ہاتھی ابرہہ نے مکہ والوں پر رعب ڈالنے کے لئے اپنے ساتھ لے لئے اور غرض یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ خانۂ کعبہ کی دیواروں کو آدمی گرائیں زنجیریں باندھ کر خانۂ کعبہ کی چاروں دیواروں کو دو دو تین تین ہاتھیوں سے باندھ دیا جائے گا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کی چاروں دیواروں کو منہدم کر دیا جائے گا.اس طرح عربوں پر بہت زیادہ رعب پڑے گا اور خانۂ کعبہ کا بھی نعوذ باللہ چند منٹ میں صفایا ہو جائے گا.یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھنے والی ہے جو میری اس پہلی دلیل کا مزید ثبوت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے تمام مذاہب میں موعودِ ادیان کی آمد کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا اور عیسائیوں کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر یہ رَو جاری رہی اور عرب میں کوئی مدعیٔ نبوت پیدا ہو گیا تو خانۂ کعبہ کے ذریعہ ان کو جو اتحاد حاصل ہے وہ اور بھی پختہ ہو جائےگا اور اہل عرب میں ایسی بیداری پیدا ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے عیسائی حکومت کا عرب سے خاتمہ ہو جائے اور خود اہل عرب کی حکومت قائم ہو جائے.میری اس دلیل کا ایک مزید ثبوت وہ روایت ہے جو جامع البیان میں علامہ طبری نے لکھی ہے اور جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ابرہہ نے محمد بن خزاعی اور اس کے بھائی قیس بن خزاعی کو مقرر کیا کہ وہ سارے عرب میں اعلان کریں کہ لوگ قلیس کے حج کے لئے آیا کریں.اس روایت سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں نے محمد نام رکھنا شروع کر دیا تھا.اور یہ ایک ایسی بات ہے جسے مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے چھوٹے درجہ کے جو عالم ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے پہلے محمد نام عرب میں تھا ہی نہیں.مگر جو اعلیٰ پایہ کےعالم ہیں
Page 331
وہ اس کے خلاف ہیں کیونکہ تاریخوں سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہوا تھا جیسے اسی روایت میں محمد بن خزاعی کا ذکر آتا ہے اور یہ اکیلا نام نہیں بلکہ تاریخوں سے ایسے پانچ نام ثابت ہیں.اس کی وجہ درحقیقت وہی ہے جو میں پہلے بیان کرچکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب میں بھی اور یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ عنقریب کوئی ظہور ہونے والا ہے.خود عیسائی مؤرخین نے لکھا ہے کہ ان میں یہ روایت تھی کہ آنے والے نبی کا نام محمد ہو گا.معلوم ہوتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے اس قسم کی پیشگوئیوں کو سن کر ان کا ذہن اس طرف مائل ہو اکہ جب آنے والے موعود کا نام محمد بتایا جاتا ہے تو ہم اپنے بچوں کا نام محمد کیوں نہ رکھ دیں.شاید ہمارا بچہ ہی وہ موعود بن جائے جس کی آمد کا انتظار کیا جارہا ہے.عیسائی کتب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میں یہ ذکر تھا کہ آنے والے موعود کا نام محمد ہو گا چنانچہ برنباس کی انجیل جس کو عیسائی ہمیشہ دباتے رہے ہیں.اس میں صاف طور پر لکھا تھا کہ محمد نامی ایک شخص ظاہر ہونے والا ہے.پس یہ محمد نام بھی بتاتا ہے کہ اس وقت لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوچکا تھا کہ آنے والا آرہا ہے اور اس کا نام محمد ہو گا.چنانچہ لوگ تفاول کے طور پر اپنے بچوں کا نام محمد رکھنے لگ گئے.وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا بچہ ہی وہ خوش قسمت بچہ بن جائے جس کے متعلق تمام مذاہب میں پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں اور جس کی آمد کا شدت سے انتظار کیا جارہا ہے.چنانچہ تاریخ سے پانچ آدمی ایسے ثابت ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ میں ہوئے.اور جن کا نام محمد تھا.وہ لوگ جن کا نام تو محمد تھا مگر تاریخوں میں ان کا ذکر نہیں ان کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قریب زمانہ کو نظرانداز کرتے ہوئے ہمیں ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ عربوںنے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہو.ان کا پہلے اپنے بچوں کا نام محمد نہ رکھنا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی بعثت کے قریب زمانہ میں ان کانام محمد رکھنا بتاتا ہے کہ اس وقت ان کےد لوں میں یہ احساس پیدا ہو چکا تھا کہ اب وہ موعود عنقریب ظاہر ہونےو الا ہے اور لوگوں نے تفاول کے طور پر اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا تھا.بہرحال ابرہہ کو جب محمد بن خزاعی کے مارے جانے کی خبر ملی تو اس کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا.اور خانہ کعبہ کے گرانے کا اور بھی زیادہ خیال اسے پیدا ہوا(جامع البیان زیر آیت تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ).یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محمدبن خزاعی کا مارا جانا اسے مکہ پر حملہ کرنے کا کوئی سیاسی حق نہیں دیتا تھا.کیونکہ خزاعہ قبیلہ یمن کے ماتحت نہیں تھا.عربوں کا اپنے کسی آدمی کو اس کی غداری کی وجہ سے مار دینا ابرہہ کے لئے حملہ کی کوئی سیاسی وجہ پیدا نہیں کرتا.اپنے آدمی کو ہر قوم مار سکتی ہے گو اس کا یہ فعل ظالمانہ ہو.یہ ذکر میں نے اس لئے کیا ہے کہ ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ چونکہ محمدبن خزاعی کو مارا گیا تھا اس لئے
Page 332
ابرہہ نے اگر حملہ کیا تو سیاسی لحاظ سے یہ حملہ جائز تھا.میں نے بتایا ہے کہ اس کا مارا جانا بالکل اور چیز ہے یہ عرب کا باشندہ تھا اور ایک عرب نے ہی اس کو مارا تھا اور قومی طور پر نہیں ذاتی طور پر مارا تھا.خزاعہ قبیلہ یمن کے ماتحت نہیں تھا کہ اسے حملہ کی کوئی سیاسی وجہ بنایا جا سکتا.جب ابرہہ نے لشکر جمع کرنا شروع کیاتو اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو خاص اہمیت دینے کے لئے لوگوں کی توجہ اس کی طرف پھرا دی.اور عربوں میں مقابلہ کا ایک عام جوش پیدا ہو گیا.پہلے یمن کے لوگوں میں جوش پیدا ہوا اور پھر انہیں دیکھ کر باقی عرب میں جوش پیدا ہو گیا.حمیری خاندان کے جو جرنیل زندہ تھے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیادت قائم کرنے اور دوبارہ بادشاہت حاصل کرنے کے لئے سارے عرب میں جوش پھیلانا شروع کر دیا اور ان سے کہا کہ تم نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا اب تم نے دیکھا کہ ابرہہ تمہاری قوم کو برباد کرنے اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لئے عرب پر حملہ کر رہا ہے.اب بھی موقع ہے اگر تم اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آؤ ہم سب مل کر ابرہہ کا مقابلہ کریں.چنانچہ ذونفر حمیری اس تحریک کا لیڈر بنا.یہ یمن کا باشندہ اور رئیس اور سابق شاہی خاندان میں سے تھا اس نے خانۂ کعبہ کی حفاظت کے نام سے یمن میں ایک عام جوش پید اکر دیا اور یمن کے تمام عرب قبائل اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے.جوں ہی ابرہہ صنعاء سے نکلا یہ لشکر اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور دونوں لشکروں کی آپس میں مڈبھیڑ ہو گئی.ان لوگوں میں بے شک مذہبی جوش تھا، قومی حمیّت تھی مگر یمن کی حکومت رومی حکومت کا ایک حصہ تھی اور اس کی فوج باقاعدہ تربیت یافتہ تھی.بے شک ان میں بھی نظام تھا مگر ان کا نظام اور ابرہہ کی باقاعدہ فوج کا نظام ایسا ہی تھا جیسے انگریزی حکومت کے مقابلہ میں قبائلیوں کو پیش کیا جائے.ان کے پاس سامان زیادہ تھا پھر وہ چھاؤنیوں میں ورزشیں کرتے رہتے تھے اور وہ ساری کی ساری فوج تنخواہ دار تھی ان کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا تھا.چنانچہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ بڑی بے جگری سے لڑے اور انہوں نے اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کی.مگر آخر شکست کھائی اور ابرہہ نے ذونفر کو قید کر لیا.ابرہہ ذونفر کو قتل کرنے لگا تو اس نے کہا.’’میرے قتل میں تو اتنا فائدہ نہ ہو گا اگر مجھے قید کر کے ساتھ رکھا جائے تو زیادہ فائدہ ہو گا.‘‘ (جامع البیان زیر آیت تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ) یہ فقرہ بظاہر معمولی نظر آتا ہے مگر اس میں ایک بہت بڑی بات پوشیدہ ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ذونفر کو یقین تھا کہ ابھی عرب کے اور کئی قبائل ابرہہ سے لڑنے کے لئے آئیں گے.اور ابرہہ کے لئے مشکلات پیدا ہوں گی.اگر میں اس کے ساتھ رہا تو اس بارہ میں کچھ کام کر سکوں گا اور بعد میں اس سے نفع اٹھاؤں گا آخر زندہ رہنے سے اسے اور کیا فائدہ ہو سکتا تھا.اس کا یہ کہنا کہ میرے قتل میں فائدہ نہیں بلکہ قید کر کے ساتھ رکھنے میں فائدہ ہے
Page 333
بتاتا ہے کہ ذونفر سمجھتا تھا کہ ابھی آئندہ اور کئی قبائل ابرہہ سے لڑنے کے لئے آئیں گے.اگر مجھے زندہ رکھو گے تو درمیانی صلح کرانے والے کے طور پر مجھ سے کام لے سکتے ہو.اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ابرہہ کے اس ارادہ سے سارے عرب میں ایک آگ لگ چکی تھی اور تمام عرب سمجھتے تھے کہ اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے.اس کے بعد ابرہہ کا لشکر شمال کی طرف اور بڑھا اور بڑھتے بڑھتے خثعم قبیلہ کی زمین پر پہنچا.طائف اور یمن کے درمیان اس قبیلہ کا علاقہ ہے.وہاں ایک دوسرا عرب لشکر اس کے مقابلہ کے لئے تیار تھا جو نفیل بن حبیب الـخثعمی کی زیر قیادت تھا.اس لشکر میں قبیلۂ خثعم کے بھی آدمی تھے اور شہدان اور ناعس کے بھی لوگ تھے.شہدان اور ناعس بعض لوگوں کے نزدیک خثعم کا ہی حصہ ہیں اور بعض کے نزدیک یہ علیحدہ قبائل تھے.انہوں نے بھی مل کر خانۂ کعبہ کی حفاظت کے لئے ابرہہ کا مقابلہ کیا مگر پھر وہی بات ہوئی.یہ لوگ قبائلی تھے جو چھٹے مہینے یا سال میں ایک دفعہ لڑنے کے لئے چلے جاتے تھے اور وہ باقاعدہ منظم فوج تھی جو چھاؤنیوں میں تربیت حاصل کرتی تھی اور روزانہ فوجی مشقیں اور ورزشیں کرتی تھی.اس کا اور ان کا مقابلہ ہی کیا ہو سکتا تھا.نہ فنون جنگ کا علم رکھنے کے لحاظ سے دونوں کی کوئی نسبت تھی اور نہ سامان کے لحاظ سے کوئی نسبت تھی.یہ لوگ بڑی بے جگری سے لڑے اور ان میں سے بہت سے مارے گئے.اور بہت سے زخمی ہوئے مگر آخر انہوں نے بھی شکست کھائی اور نفیل بن حبیب الـخثعمی قید کر لیا گیا.اسے بھی ابرہہ نے قتل کرنا چاہا مگر جب نفیل نے کہا کہ مجھے زندہ رکھنے سے شہدان اور ناعس کے قبیلوں پر اس کا اثر بڑھ جائے گا.تو اس نے اسے زندہ رکھا اور راستہ دکھانے کے لئے اپنے ساتھ لے لیا.اس سے پتہ لگتا ہے کہ عربوں میں اس وقت ایمان بہت کمزور ہو چکا تھا.یوں وہ بڑی دلیری سے لڑتے تھے مگر جب اپنی جان کا سوال آتا تو لالچ میں آجاتے.یہی نفیل نے کیا.جب اسے قتل کیا جانے لگا تو اس نے ابرہہ کو اپنی خدمات پیش کر دیں اور کہا کہ آگے جنگل ہے.آپ کو راستہ ملنا مشکل ہو گا.اگر مجھے زندہ رکھا جائے تو میں لشکر کو خانۂ کعبہ تک پہنچادوں گا.چنانچہ بادشاہ نے اس کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اسے قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا.یہ لشکر پھر اور آگے بڑھا.جب طائف کے قریب پہنچا تو طائف کا سردار مسعود بن معتب جو ثقیف قوم میں سے تھا (یہی قوم ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زمانۂ بچپن گذارا ہے.اور یہی قوم ہے جس سے آپؐکی وہ آخری جنگ ہوئی جسے غزوۂ حنین کہتے ہیں) ثقیف قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو لے کر بادشاہ کے استقبال کو نکلا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لات بُت جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے اور جس کا ذکر بعض دفعہ اردو شعراء بھی اپنے کلام میں کر لیتے ہیں.اس کا بُت خانہ اسی طائف میں تھا اس نے آگے آکر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ہم کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں.عجیب بات یہ ہے کہ طائف والے
Page 334
بھی خانۂ کعبہ کو مانتے تھے بلکہ حج بھی کرتے تھے مگر پھر بھی لات کی وجہ سے انہیں خانۂ کعبہ سے رقابت تھی اور وہ محسوس کرتے تھے کہ خانۂ کعبہ کی موجودگی میں ہمارا بت خانہ لوگوں کا مرجع نہیں بن سکتا.اس کی کچھ یہ بھی وجہ تھی کہ طائف کے لوگ بڑے مالدار تھے اور ان کی زمین بڑی اعلیٰ درجہ کی تھی وہاں کا انگور اور انار اتنا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے کہ دنیا میں اور کہیں اس قسم کا انگور اور انار نہیں ملتا.یورپ کے لوگ اٹلی کے انگو رکو سب سے بہتر سمجھتے ہیں مگر میں نے سفر یورپ میں اٹلی کا انگور بھی کھایا ہے اور طائف کا انگور بھی میں کھا چکا ہوں میں سمجھتا ہوں اگر طائف کے انگور کو میں سو نمبر دوں تو اٹلی کے انگور کو میں صر ف دس نمبر دے سکتا ہوں.طائف کے مقابلہ میں اٹلی کے انگور کی کوئی نسبت ہی نہیں.انار بھی میں نے کسی جگہ کا اتنا میٹھا نہیں دیکھا جس کو کھا کے منہ میٹھے سے پھر جائے.لیکن طائف کا انار ایسا ہے کہ اس کے کھانے سے منہ میٹھے سے پھر جاتا ہے.بہت ہی تیز مٹھاس اس میں ہوتی ہے.پس چونکہ وہ مالدار تھے اور پھر لات کا بت خانہ بھی طائف میں تھا.اس لئے وہ مکہ والوں سے رقابت رکھتے تھے اور ان کو یہ خیال رہتا تھا کہ ہمارا مندر کیوں اتنا بڑا نہیں سمجھا جاتا جتنا خانۂ کعبہ سمجھا جاتا ہے.چنانچہ باوجود اس کے کہ وہ حج کرنے کے لئے بھی جاتے تھے ان کی کوشش رہتی تھی کہ لات کے مندر کا رتبہ کسی طرح خانۂ کعبہ سے زیادہ ہو جائے یا کم از کم خانۂ کعبہ کے برابر ہو جائے.اب جو انہوں نے ابرہہ کو آتے دیکھا تو ان کی رقابت جوش میں آگئی اور انہوں نے سمجھا کہ ابرہہ خانۂ کعبہ کو گرادے گا تو لات کے مندر کی طرف لوگوں کی توجہ بڑھ جائے گی.چنانچہ جب ابرہہ آیا تو مسعود بن معتب اس کے استقبال کو نکلا اور اس نے ابرہہ سے کہا کہ ہم کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں اور نہ ہمیں خانۂ کعبہ سے کوئی ہمدردی ہے اور ہم تو آپ کےمطیع اور فرمانبردار ہیں.ہم آپ کے ساتھ ایک آدمی کر دیتے ہیں جو آپ کو سیدھا مکہ تک لے جائے.کیونکہ آگے وادیاں زیادہ خطرناک ہیں ممکن ہے لشکر بھٹک جائے اور وہ مکہ تک نہ پہنچ سکے.اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے جذباتِ عقیدت کو پیش کرتے ہوئے کہا ہمارے گرجا کو کچھ نہ کہیے.وہ تو کسی اور گرجا کو گرانے کے لئے نکلا ہی نہیں تھا وہ تو صرف خانۂ کعبہ کو گرانے کے لئے نکلا تھا.کیونکہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو چکا تھا کہ خانۂ کعبہ عرب کو عیسائیت کی طرف لانے میں مخل ہے.جب اس نے اپنے گرجے کا ذکر کیا کہ اسے کچھ نہ کہا جائے تو ابرہہ نے اس کی بات فوراً مان لی بلکہ اسے کچھ انعام بھی دیا.اس نے ابورغال نامی ایک شخص کو راستہ دکھانے کے لئے ابرہہ کے ساتھ روانہ کیا.جب لشکر مغمس نامی مقام پر پہنچا جو مکہ کے بالکل قریب ہے تو وہاں ابورغال مر گیا اور اس کی قبر وہاں بنائی گئی.عرب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک بلکہ بعد میں بھی (میں کہہ نہیں سکتا کہ اب وہ قبر ہے یا نہیں مجھے ذاتی طو رپر اس کا کوئی علم نہیں) جب بھی اس قبر کے
Page 335
پاس سے گذرتے تو اسے پتھر مارتے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ یہ لعنتی آدمی ہے.جس نے اپنے مذہب اور قوم سے غداری کرکے ابرہہ اور اس کے لشکر کو راستہ دکھایا.ابرہہ کا لشکر کہاں تک پہنچا اور آیا وہ مغمس مقام سے بھی آگے بڑھا ہے یا نہیں، اس کے متعلق تاریخوں میں اختلاف ہے.بعض کے نزدیک وہ حدودِ حرم سے باہر ہی رہا.بعض کہتے ہیں کہ وہ عرفات تک پہنچا.اس طرح مکہ سے وہ گیارہ بارہ میل تک پہنچ گیا تھا.بعض اسے اور بھی قریب بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابرہہ اور اس کا لشکر مزدلفہ کے قریب تک پہنچ گیا تھا.اس لحاظ سے مکہ سے وہ صرف سات آٹھ میل دور رہا.بہرحال مغمس تک تو ساری تاریخیں متفق ہیں اور بتاتی ہیں کہ وہاں تک ضرور پہنچا اور مغمس کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ پندرہ سولہ میل کا ہو گا.سنن ابی داؤد کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب طائف کی طرف گئے (غزوۂ حنین کے موقعہ پر) تو ہم ایک قبر کے پاس سے گذرے.آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابورغال کی قبر ہے جو ثقیف بھی کہلاتا تھا اور ثمود قوم میں سے تھا.یہ مکہ کی حفاظت کے لئے آیا تھا.جب واپس اپنے شہر کی طرف گیا تو وہی عذاب جو اس کی قوم کو پہنچا تھا اسے بھی پہنچا اور وہ مر گیا اور اس جگہ دفن ہوا.(ابو داؤد کتاب الـخراج والفیء والامارۃ باب نبش القبور) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابورغال ابرہہ کا راہنما نہ تھا بلکہ مکہ کے محافظین میں سے تھا.کیونکہ آپؐفرماتے ہیں یہ مکہ کی حفاظت کے لئے آیا تھا.لیکن دوسری روایت بتاتی ہے کہ وہ ابرہہ کو راستہ دکھانے آیا تھا.یہ دونوں روایتیں بظاہر بالکل بے جوڑ معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ایک روایت تو اسے خانۂ کعبہ کا دشمن بتاتی ہے اور تاریخ سے بھی ثابت ہے کہ عرب اس کی قبرکو پتھر مارا کرتے تھے(روح المعانی زیر آیت ۱تا ۵) مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فرماتے ہیں کہ ابورغال مکہ کی حفاظت کے لئے آیا تھا.اس پر بعض نے تو کہا ہے کہ ان میں سے صرف ایک روایت صحیح ہے.چنانچہ وہ سنن ابی داؤد میں بیان شدہ روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں دوسری روایت کو غلط بتاتے ہیں.لیکن بعض کہتے ہیں کہ دوسری روایت بھی تاریخی لحاظ سے اس قدر یقینی ہے کہ ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے(روح المعانی زیر آیت ۱تا ۵).اس مشکل کا حل مفسرین نے اس طرح کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دوالگ الگ شخص تھے مگر دونوں کا نام ایک تھا.ایک ابورغال وہ تھا جو مکہ کی حفاظت کے لئے آیا تھا اور ایک ابورغال وہ تھا جو ابرہہ کا راہنما بن کر آیا تھا.پس قبریں بھی دو الگ الگ تھیں.اگر الگ الگ نہ ہوتیں تو قبر دکھاتے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مکہ کا محافظ تھا تو اہل عرب آپ سے یہ نہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ اس کو تو ہم پتھر مارا کرتے ہیں اور اسے باغی اور غدار سمجھتے ہیں اور آپ اسے
Page 336
محافظ کعبہ قرار دے رہے ہیں؟ (روح المعانی زیر آیت ۱تا ۵) پس معلوم ہوا کہ یہ قبر کسی دوسرےابورغال کی تھی اسی لئے آپ سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ابورغال ابرہہ کےساتھ آیا اور مر گیا اور ایک ابورغال وہ تھا جس نے حفاظتِ کعبہ میں حصہ لیا اور بعد میں مرا.یہ بھی ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اور ابورغال تھا.وہ ابورغال تو ابھی عذاب آیا ہی نہیں تھا کہ مر گیا تھا اور یہ ابورغال عذاب آنے کے بعد مرا.میں سمجھتا ہوں مغمس میں پہنچتے ہی ابورغال کی جو موت واقعہ ہو گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ آخر ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ تو ایمان تھا اور وہ خانۂ کعبہ کو مقدس تسلیم کرتے تھے.جب وہ راہنما بن کر نکلا تو اس کے دل پر قدرتی طور پر اس کا بوجھ پڑا کہ میں کیسی غداری کر رہا ہوں اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا.پس ابورغال دو تھے ایک ابورغال حفاظت کعبہ کے لئے مکہ میں رہا اور جب واپس اپنی قوم کی خبر لینے کے لئے گیا تو اسی بیماری کا شکار ہو گیا جو اصحاب فیل اور اس کی قوم میں پُھوٹ پڑی تھی اور دوسرا ابورغال وہ تھا جو ابرہہ کے لشکر کے ساتھ اس کا راہنما بن کر آیا اور کسی وجہ سے رستہ میں ہی مر گیا.میرے خیال میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا کیونکہ اس کے دل پر اپنی غداری کا ایسا بوجھ پڑا کہ وہ اس کی برداشت نہ کر سکا اور موت کا شکار ہو گیا.جب مغمس مقام پر ابرہہ کا لشکر پہنچا تو اس نے اسود بن مقصود حبشی کو روانہ کیا کہ وہ کچھ فوج اپنے ساتھ لے جائے اور مکہ کا حال معلوم کر کے آئے(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام امر الفیل و قصۃ النسأۃ).اس نام سے بھی پتہ لگتا ہے کہ حبشہ کی زبان اس وقت بہت کچھ عربی زبان سے ملتی جلتی تھی.میں نے بتایا تھا کہ حبشی زبان ایک طرح عربی کی ایک شاخ تھی جس طرح کہ عبرانی زبان عربی کی شاخ ہے.عربی اور حبشی زبان کے بہت سے الفاظ آپس میں ملتے ہیں اور کثرت کے ساتھ ان میں سے ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں.نام بھی بہت کچھ ملتے جلتے ہیں.چنانچہ اسی اسود بن مقصود نام کو دیکھ لو مقصود عربی نام ہے.اسی طرح ابرہہ اور یکسوم کا وزن عربی اوزان میں سے ہے(لسان العرب).اب بھی ان دونوں زبانوں میں بہت کچھ مشارکت پائی جاتی ہے لیکن اس زمانہ میں تو یہ مشارکت بہت بڑھی ہوئی تھی اصل میں حبش کے حاکم لوگ عربی النسل تھے اور موجودہ شاہی خاندان بھی اسی عربی نسل میں سے ہے اسی وجہ سے یہ دونوں زبانیں آپس میں ملتی جلتی ہیں.بہرحال اس نے اسود بن مقصود حبشی کو کچھ فوج دے کر روانہ کیا تاکہ وہ مکہ کا حال معلوم کر کے واپس آئے.وہ فوج کا ایک دستہ لے کر مکہ کے قریب پہنچا.مکہ کے اردگرد بہت سی وادیاں ہیں جن میں جانور چرتے رہتے ہیں.اس نے مکہ والوں کے جانور ان وادیوں میں چرتے دیکھے.جب وہ ضروری معلومات حاصل کر چکا تو آتی دفعہ وہ ان
Page 337
جانوروں کو بھی ہانک کر اپنے ساتھ لے آیا(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام امر الفیل و قصۃ النسأۃ).مکہ والوں کی بڑی جائیداداونٹ تھی.گھوڑا عرب میں بہت کم ہوتا ہے.۱۹۱۲ء میں جب میں حج کے لئے گیا تو سارے مکہ میں صرف تین چار گھوڑے تھے اب میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کیا حالت ہے.عرب کا گھوڑا جو دنیا میں مشہور ہے وہ مشرق کے علاقہ میں ہوتاہے یعنی نجد اور اس کے اطراف میں شام وغیرہ میں بھی لوگ گھوڑے رکھتے ہیں لیکن حجاز میں گھوڑے کا بہت کم رواج ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں چارہ نہیں ہوتا.اونٹ تو درختوں کے پتے اور کانٹے وغیرہ کھا لیتا ہے مگر گھوڑا یہ چیزیں نہیں کھا سکتا اس لئے عرب کی بڑی جائیداد اونٹ ہی ہوتی ہے اور پرانے زمانہ میں بھی یہی ان کی جائیداد تھی.جس طرح ہمارے ملک میں رواج ہے کہ وہ ایک آدمی کو اس غرض کے لئے مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ جانوروں کو باقاعدہ باہر لے جائے اور پھر گھروں میں شام کو واپس لے آئے اور ماہوار اسے کچھ رقم دے دیتے ہیں یہی دستور مکہ میں بھی تھا.لیکن اونٹوں کے متعلق یہ دستور ہے کہ انہیں روزانہ شام کو واپس نہیں لاتے بلکہ چھ چھ سات سات دن یا اس سے بھی زیادہ باہر رکھتے ہیں البتہ کبھی کبھی وہ مالک کو دکھانے کے لئے لے بھی آتے ہیں.مکہ سے دو دو تین تین منزل پر جہاں کچھ درخت اور کانٹے وغیرہ ہیں وہ اپنے جانور بھیج دیتے تھے.اسی دستور کے مطابق اس روز بھی مکہ والوں کے جانور باہر گئے ہوئے تھے جب اسود حالات معلوم کر کے واپس آنے لگا تو وہ ان اونٹوں کو بھی ہانک لایا.ان میں حضرت عبدالمطلب کے بھی دو سو اونٹ تھے.جب یہ لوگ خبر رسانی کے لئے مکہ کے قریب آئے اور انہوں نے حالات معلوم کئے تو مکہ والوں نے سمجھ لیا کہ اب حملہ سر پر پہنچ گیا ہے.چنانچہ انہوں نے ایک اجتماع کیا جس میں کنانہ ھذیل اور قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے غور کرنا شروع کیا کہ ہمیں ابرہہ کا مقابلہ کرنا چاہیے یانہیں.کنانہ وہ قوم ہے جس میں سے قریش نکلے ہیں.صرف قریش ہی بنو اسمٰعیل نہیں، بنواسمٰعیل تمام عرب میں پھیلے ہوئے تھے.قریش صرف کنانہ کے ایک بیٹے کی نسل کا نام ہے.بہرحال قریش نے اور ھذیل اورکنانہ کے سرداروں نے مل کر مشورہ کیا اور غور کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے.مشورہ میں ہر ایک کی رائے یہی تھی کہ ہم میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں اس لئے مقابلہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.چنانچہ یہ ارادہ ترک کر دیا گیا(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام امر الفیل و قصۃ النسأۃ).میں بتا چکا ہوں کہ ابرہہ اس لئے نہیں آیا تھا کہ وہ عربوں کو کوئی تکلیف پہنچائے یا مکہ والوں کو کوئی سزا دے اس کی غرض صرف یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو گرا دے اور عربوں کی توجہ اس مرکز کی طرف نہ رہے اس کے بعد یا تو ان کی توجہ صنعاء کی طرف پھر جائے یا وہ پراگندہ ہو جائیں.ان کے اکٹھے ہونے کی کوئی صور ت نہ رہے اس نے اسی بات کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے ایک خاص آدمی مکہ والوں کی طرف بھجوایا جو
Page 338
حمیری قبیلہ کا تھا اور جس کا نام حیاطہ تھا اور اس کے ذریعہ یہ پیغام بھجوایا کہ میں صرف خانۂ کعبہ کو گرانے کے لئے آیا ہوں تم لوگوں کو کسی قسم کی گزند پہنچانے کا میرا ارادہ نہیں اور چونکہ مکہ والوں سے میری کوئی دشمنی نہیں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ تم خواہ مخواہ اپنی جانیں ضائع کرو.تم اگر ایک طرف ہو جاؤ اور مجھے خانہ کعبہ کو گرا لینے دو تو تم میرے بھائی ہو مجھے تم سے کسی قسم کا بگاڑ مطلوب نہیں(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام امر الفیل و قصۃ النسأۃ ).یہ سردار جب مکہ پہنچا تو اس نے دریافت کیا کہ مکہ کا سردار آج کل کون ہے.لوگوں نے حضرت عبدالمطلب کا نام لیا کہ وہ سردار ہیں وہ حضرت عبدالمطلب کے پاس گیا اور ان کو ابرہہ کا پیغام دیا انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر اس کی ہم سے لڑنے کی نیت نہیں تو ہماری بھی اس سے لڑنے کی نیت نہیں.پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہم ہرگز ابرہہ سے لڑائی کرنا نہیں چاہتے.اور سچائی سے کام لیتے ہوئے صاف کہہ دیا کہ ہم نے غو رکر کے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم میں لڑائی کی طاقت نہیں اس لئے مقابلہ نہ کیا جائے.ابرہہ جو فوج اپنے ساتھ لایا تھا اس کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ اس کی ۱۲ ہزار کی تعداد تھی اور بعض بیس ہزار بتاتے ہیں(تفسیر ابن کثیر زیر آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ) گویا ایک پورا ڈویژن وہ اپنے ساتھ لایا تھا.اور اتنی بڑی فوج سے تو بعض دفعہ ایک ملک کا ملک فتح کر لیا جاتا ہے.جب محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے تو ان کے ساتھ صرف تین ہزار آدمی تھے.پس چونکہ ابرہہ ایک بھاری فوج لے کر آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم کسی احسان کے اظہار کے لئے نہیں بلکہ امر واقعہ کے طور پر کہتے ہیں کہ ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں باقی یہ گھر جسے ہم مانتے ہیں اس کے متعلق ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہو اہے اور ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ؑ جو اللہ تعالیٰ کے دوست اور اس کے نبی اور اس کے پیارے تھے انہوں نے اس گھر کو بنایا تھا پس ہم اپنے متعلق تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس گھر کو بچانا چاہے تو یہ گھر اس کا ہے اور اس کا ادب اور احترام اس کے ذمہ ہے.پس اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت نہ ہو کہ وہ اس گھر کی حفاظت کرے بلکہ وہ چاہتا ہو کہ اس گھر کو چھوڑ دے اور ابرہہ کے لشکر کو اجازت دے دے کہ وہ اس گھر کو توڑ دے تو اس گھر کو بچانے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں.اس پر حیاطہ نے کہا کہ اگر آپ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تو بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ابرہہ نے بھی خواہش کی تھی کہ میں مکہ کے کسی رئیس کو اپنے ساتھ لاؤں آپ میرے ساتھ چل کر ابرہہ پر روشن کر دیں کہ آپ کا ارادہ کسی قسم کی لڑائی کا نہیں اس سے ابرہہ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور ممکن ہے وہ خانۂ کعبہ کو گرانے کا ارادہ ترک کر دے.اس پر حضرت عبدالمطلب نے اپنے لڑکوں اور بعض رؤوسا کو ساتھ لیا اور ابرہہ سے ملنے کے لئے مغمس مقام
Page 339
پر پہنچے.چونکہ عرب کے لوگ جیسا کہ اگلی سورۃ میں ذکر آئے گا اکثر سفر کرتے رہتے تھے.بعض یمن کی طرف جاتے تھے ،بعض شام کی طرف جاتے تھے، بعض حبشہ کی طرف جاتے تھے، بعض عراق کی طرف جاتے تھے(تاریخ مکہ مکرمہ زیر عنوان معاشی استحکام صفحہ ۱۹۵).اس لئے ان علاقوں کے رہنےو الے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں اور تعلقات تھے انہی سفروں کی وجہ سے حضرت عبدالمطلب کے بھی ذونفر حمیری کےساتھ تعلقات تھے جو دوستانہ حد تک پہنچے ہوئے تھے.جب باتوں باتوں میں انہیں حیاطہ سے معلوم ہوا کہ ذونفر نے بھی مکہ کے بچانے کے لئے ایک لشکر جمع کیا تھا اور ابرہہ کے ساتھ لڑائی بھی کی تھی جس میں اسے شکست ہوئی اور وہ قید کر لیا گیا اور اب بھی وہ ابرہہ کےساتھ ہی ہے تو حضرت عبدالمطلب کو خیال آیا کہ میں پہلے ذونفر سے ملوں گا وہ یمن کا رہنے والا ہے اور بادشاہ کی عادات اور حبشہ قوم کے خصائل سے اچھی طرح واقف ہے ممکن ہے وہ اس بارہ میں مجھے کوئی مفید مشورہ دے سکے.چنانچہ جب کیمپ میں پہنچے تو انہوں نے پتہ لیا کہ ذونفر کہاں ہے.وہ بے شک قید تھا مگر اس زمانہ کی قید اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ مجرموں کو کوٹھڑیوں میں بند رکھا جاتا بلکہ صرف ان کی نگرانی ہوتی تھی.جیسے آج کل نظربندوں کی نگرانی کی جاتی ہے.حضرت عبدالمطلب لوگوں سے پتہ دریافت کرتے ہوئے ذونفر کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ ذونفر تم کو کعبہ اور کعبہ والوں کی کوئی پروا نہیں یعنی اگر تمہارے دل میں کعبہ کی محبت ہوتی یا ہماری دوستی کا تمہیں کچھ پاس ہوتا تو تم کوشش کرتے کہ یہ حملہ ٹل جائے ذونفر نے جواب میں کہا کہ ایک قیدی جسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شام تک زندہ رہے گا یا نہیں اور جسے شام کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صبح تک زندہ رہے گا یا نہیں، اس کی پروا یا عدم پروا کا سوال ہی کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو اس وقت کلی طو رپر بادشاہ کے رحم پر ہوں.وہ چاہے تو شام کو قتل کروا دے اور چاہے تو صبح کو قتل کروا دے.باقی جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا.ابرہہ سے میں نے لڑائی بھی کی مگر مجھے شکست ہوئی اور میں قید ہوگیا.اب میری رائے کا کیا سوال ہے اور میں اس بارہ میں کیا کر سکتا ہوں.میرے دل کی تو یہی خواہش ہے کہ تم لوگ بچو مگر یہ میرے بس کی بات نہیں.ہاں میں نے قید کے زمانہ میں شاہی ہاتھی کے مہاوت انیس نامی سے دوستی پیدا کر لی ہے(روح المعانی زیر آیت ھذا) وہ میرا ادب اوراحترام بھی کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں اس مہاوت سے آپ کو ملوا دیتا ہوں اور اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ موقع ملنے پر وہ آپ لوگوں کے متعلق کوئی نیک بات بادشاہ کے کان میں ڈال دے.پرانے زمانہ میں یہ ایک عام دستور تھا اور ہندوستان میں بھی یہ دستور ایک لمبے عرصہ تک رہا ہے کہ بادشاہ اپنے نوکروں کی بات بہت کچھ مانتے تھے اور ان کی بات کو ردّ کرنا شانِ کبریائی کے خلاف سمجھتے تھے معلوم ہوتا ہے ان میں بھی یہی رواج تھا.انیس چونکہ بادشاہ کا منہ چڑھا نوکر تھا اور گو مہاوت کا عہدہ بھی بڑا بھاری عہدہ ہوتا ہے
Page 340
کیونکہ مہاوت پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور بادشاہ کی جان کی حفاظت اس کے ذمہ ہوتی ہے مگربہرحال یہ عہدہ ویسا تو نہیں جیسے کرنیل یا جرنیل کا عہدہ ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک بڑے شافر جیسی سمجھنی چاہیے مگر چونکہ اس کی بات سنی جاتی تھی اس لئے ذونفر نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں انیس سے آپ کی ملاقات کرا دوں.حضرت عبدالمطلب کو اس وقت کوئی راہ نظر نہ آتی تھی آپ نے اس کی بات کو بھی خوشی سے قبول کیا.اس پر ذونفر نے انیس کو بلوا بھیجا اور اس سے کہا کہ عبدالمطلب قریش کے سردار ہیں اور غریبوں کا خاص خیال رکھنے والے ہیں.انسان چھوڑ جانوروں تک کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے دو سو اونٹ شاہی سوار پکڑ کر لے آئے ہیں.ان کو بادشاہ سے ملواسکو اور کوئی نیک سفارش ان کے متعلق کر سکو تو کوشش کرو.اس نے کہا بہتر ہے اور وہ حضرت عبدالمطلب کو اپنے ساتھ لے گیا.پرانے زمانہ میں یہ طریق تھا کہ جب جانور وغیرہ ذبح کئے جاتے تو لوگ ان کا کچھ حصہ چیلوں اور کتوں کے لئے بھی رکھ لیتے تھے.اب بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں.ان کے اسی وصف کی طرف اس وقت ذونفر نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ انسانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور دوسرے جانوروں کا بھی خیال رکھتے ہیں.وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا اور شاہی خیمہ کے دروازہ کے پاس جا کر اس نے کہا حضور اجازت دیں عبدالمطلب جو مکہ کے رئیس ہیں وہ آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں.پھر اس نے وہی بات دہرائی جو ذونفر نے کہی تھی کہ یہ بڑے محسن ہیں تمام انسانوں اور غریبوں کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں بلکہ وحشی جانوروں تک کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر یہ فقرہ بھی بڑھا دیا کہ حضور ان کی طرف نظرِ التفات رکھیں بادشاہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی.حضرت عبدالمطلب بڑے مضبوط، قوی الجثہ، لمبے قد والے، چوڑے چکلے جسم والے اور سفید رنگ کے انسان تھے جب آپ خیمہ ٔ دربار میں داخل ہوئے اور ابرہہ نے اپنے سامنے ایک نہایت وجیہ خوبصورت، چوڑے چکلے جسم والا قد آور اور مضبوط انسان پایا تو وہ آپ کی شکل اور قد و قامت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا.(حبشہ کے لوگوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے) چنانچہ آپ کے داخل ہوتے ہی وہ کھڑا ہو گیا.اس کے بعد اس نے پہلے تو یہ چاہا کہ آپ کو اپنے ساتھ ہی تخت پر بٹھا لے مگر پھر خیال آیا کہ اگر میں نے انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا تو حبشی قوم ناراض ہو جائے گی کہ شاہی مقام کی بے حرمتی کی گئی ہے مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو نیچے بٹھائے اور خود اونچا بیٹھا رہے.آخر خیمہ میں جو قالین بچھا ہوا تھا اس پر وہ خود بھی بیٹھ گیا اور حضرت عبدالمطلب کو بھی اس نے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ترجمان کوبلا کر کہا کہ ان سے کہو کہ مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے.آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آنے کی کیا غرض ہے اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں.ترجمان نے ان سے کہا کہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اور وہ دریافت کرتے ہیں کہ آپ کس
Page 341
غرض کے لئے آئے ہیں؟ حضرت عبدالمطلب نے ترجمان سے کہا کہ بادشاہ سے کہو آپ کے آدمی میرے دو سو اونٹ پکڑ کر لے آئے ہیں وہ مجھے واپس کر دیئے جائیں جب اس جواب کا ترجمہ کر کے ابرہہ کو سنایا گیا تو اس نے ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو جب میں نے آپ کی شکل دیکھی تھی تو میں بہت ہی متاثر ہوا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے عقلمند، لائق اور تجربہ کار انسان ہیں.اسی لئے میں آپ سے ملنے کے لئے تخت سے نیچے اتر آیا.مگر اب جو میں نے آپ کی بات سنی ہے تو میرے دل سے وہ سب اثر جاتا رہا ہے.آپ نے سنا ہو گا کہ میں ایک بڑی فوج لے کر اس لئے آیا ہوں کہ اس مقام کو جو آپ کے اور آپ کے باپ دادوں کا عبادت گاہ ہے گرادوں.میں مانتا یا نہ مانتا لیکن اس حسن ظنی کی وجہ سے جو مجھے آپ پر تھی میں یقین رکھتا تھا کہ آپ میرے سامنے یہی بات پیش کریں گے کہ ہمارے مقدس مذہبی مقام کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ.مگر آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا حالانکہ وہ آپ کی عبادت گاہ ہے اور نہ صرف آپ کی عبادت گاہ ہے بلکہ آپ کے باپ دادا کی بھی یہی عبادت گاہ رہی ہے.آپ نے میرے پوچھنے پر اگر ذکر کیا تو یہ کہ میرے دو سو اونٹ واپس کر دیئے جائیں بھلا یہ بھی کوئی اونٹوں کے ذکر کرنے کا موقع تھا.پس مجھے تعجب ہے کہ آپ نے ان دو سو اونٹوں کا تو ذکر کیا جو آپ کی ملکیت تھے اور جن کو میرے آدمی لے آئے تھے مگر اس گھر کو بھول گئے جس سے آپ کا اور آپ کے باپ دادوں کا دین وابستہ ہے.حضرت عبدالمطلب نے جب یہ بات سنی تو ترجمان سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے کہہ دو اونٹوں کا مالک میں ہوں اور میں نے آپ سے جو اونٹ مانگے ہیں یہی بتانے کے لئے مانگے ہیں کہ وہ اونٹ میرے ہیں اور میرے دل میں ان کا درد ہے.اگر خانۂ کعبہ بھی کسی کا گھر ہے تو اس کے دل میں بھی اس کا درد ہو گا.پس میرا مطالبہ غلط نہیں بلکہ میں نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ اس گھر کے متعلق صحیح ہے تو پھر آپ اس گھر پر حملہ کر کے نہیں بچیں گے.کیونکہ اگر مجھے اونٹوں کی فکر ہے تو کیا کعبہ جس کا گھر ہے اسے یہ فکر نہیں ہو گی کہ وہ اسے آپ کے حملہ سے بچائے؟ باقی ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہے.اگر ہم لڑ کر مارے جائیں اور آپ پھر بھی اس گھر کو گرا دیں تو ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا ہے اور اگر خدا نے اس گھر کو بچانا ہے تو ہمیں لڑائی کرنے کی ضرورت کیا ہے.جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا.ابرہہ یہ جواب سن کر مبہوت سا ہو گیا.مگر اس نے کہا مجھے اس کام سے اب کوئی روک نہیں سکتا.حضرت عبدالمطلب نے کہا تو پھر آپ اور اس گھر والا آپس میں سمجھ لیں مجھے میرے اونٹ واپس دے دیئے جائیں.اس پر ابرہہ نے اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا اور حضرت عبدالمطلب کے اونٹ انہیں واپس دے دیئے گئے(روح المعانی زیر آیت ھذا).
Page 342
میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت حضرت عبدالمطلب کے ساتھ آپ کے بیٹوں کےعلاوہ جو پہرہ دار کے طور پر گئے تھے بعض اور رؤوسا بھی تھے.روایات میں آتا ہے کہ یعمر بن نفاثہ بنو کنانہ کے سردار اور خویلد بن واثلہ ہذیل کے سردار آپ کے ساتھ تھے.حضرت عبدالمطلب پر تصوّف کا رنگ غالب تھا اور اس رنگ میں انہوں نے ابرہہ سے بات کی.مگر دوسرے سیاسی ٹائپ کے آدمی تھے اور چاہتے تھے کہ انہیں بھی ابرہہ سے بات کرنے کا موقع ملے.جب حضرت عبدالمطلب بات کر چکے تو یعمر بن نفاثہ اور خویلد بن واثلہ نے کہا کہ ہم بھی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں.بادشاہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا تہامہ وادی یعنی مکہ اور اس کے اردگرد جس قدر علاقہ ہے اس تمام علاقہ کی طرف سے ہم یہ پیشکش لے کر آئے ہیں کہ آپ اس تمام علاقہ کے مال و دولت، مکانات، اونٹوں، بکریوں، گھر کے اثاثہ اور دوسری تمام چیزوں کی قیمت لگوا لیں اور اس تمام قیمت کا ۳ ۱آپ لے لیں اور ۳ ۲ہمارے پاس رہنے دیں ہماری درخواست صرف اس قدر ہے کہ آپ خانۂ کعبہ کو کچھ نہ کہیں اور اس کے گرانے کا ارادہ ترک کر دیں.بادشاہ نے کہا نہیں میں تو خانۂ کعبہ کو ہی گرانے کے لئے آیا ہوں مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں.اس پر یہ لوگ وہاں سے مکہ لوٹ آئے.مکہ واپس آنے پر حضرت عبدالمطلب نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ابرہہ سے ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے حالات سنائے اور یہ بھی بتایا کہ ہم لوگوں نے اس کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی تھی کہ وہ تہامہ کے تمام اموال کا تیسر احصہ لے لے اور خانۂ کعبہ کو چھوڑ دے.مگر اس نے اس تجویز کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے یہ حالات بتا کر انہوں نے کہا اب ابرہہ کا خانۂ کعبہ پر حملہ کرنا یقینی ہے مگر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ لشکر ہے اور نہ اس کے مقابلہ کا کوئی سامان ہے.اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم سب لوگ اس شہر کو چھوڑ دو اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈیرے لگا لو تاکہ جو کچھ ابرہہ نے کرنا ہے وہ کر لے یا جو کچھ خدا نے کرنا ہے وہ ظاہر ہو جائے اس کے بعد ہم مکہ میں واپس آجائیں گے.یہ کہہ کر حضرت عبدالمطلب کچھ قریش دوستوں کےساتھ خانۂ کعبہ کے پاس آئے.دل میں رقت تھی، سوز تھا، درد تھا.خانۂ کعبہ کے دروازہ کا حلقہ جس کو پکڑ کر دروازہ کھولتے ہیں اسے انہوں نےا پنے ہاتھ میں لیا اور اللہ تعالیٰ سے نہایت سوز کے ساتھ دعا کرتے ہوئے یہ شعر کہے لَاھُمَّ اِنَّ الْعَبْدَ یَـمْنَعُ رَحْلَہٗ فَامْنَعْ حَلَالَکْ لَا یَغْلِبَنَّ صَلِیْبُـھُمْ وَ مِـحَالُھُمْ غَدْوًا مِـحَالَکْ لَاھُمَّ یہ دراصل اَللّٰھُمَّ ہے.عربی میں دستور ہے کہ بعض دفعہ شعری ضرورت کو مدّ ِنظر رکھتے اَللّٰھُمَّ کا ال گرا دیتے ہیں اور اللہ کی جگہ صرف لا کہہ دیتے ہیں.
Page 343
لَاھُمَّ اِنَّ الْعَبْدَ یَـمْنَعُ رَحْلَہٗ فَامْنَعْ حِلَالَکْ اے اللہ جب بندے کے گھر کو کوئی لوٹنے کے لئے آتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو اپنا گھر لوٹنے نہیں دیتا فَامْنَعْ حَلَالَکَ اے رب وہ اس کا گھر ہوتا ہے جس میں وہ آپ رہتا ہے یا اس کے بیوی بچے رہتے ہیں.مگر یہ گھر ایسا ہے جس کے متعلق تو نے دنیا کے لوگوں کو کہا ہے کہ آؤ اور یہاں عبادت کرو.پس میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو بھی اپنے اس گھر کی حفاظت فرما جس میں لوگ عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور اسے دشمن کے حملہ سے بچا.لَا یَغْلِبَنَّ صَلِیْبُـھُمْ وَ مِـحَالُھُمْ غَدْوًا مِـحَالَکْ اے میرے رب کل ابرہہ اپنی صلیبیں اور لشکر لے کر اور اپنی تمام تدبیروں اورقوت اور جلال کے ساتھ خانۂ کعبہ کو گرانے کے لئے آئے گا.اے خدا ان کی صلیبیں اور فوجیں اور قوتیں تیری قدرتوں اور تدبیروں اور طاقتوں پر کل غالب نہ آئیں.یہ کہا اور قریش کو لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے اور ابرہہ کے حملہ کا انتظار کرنے لگے.دوسرے دن صبح کے وقت ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دےد یا.اس نے اعلان کیا کہ پہلے ہاتھی نکالے جائیں اور ان کے پیچھے پیچھے لشکر روانہ ہو.جب صبح کے وقت ہاتھی نکالنے گئے تو ان کا سب سے بڑا ہاتھی جس کے متعلق میں نے بتایا ہے کہ اس کا نام محمود تھا الٰہی تصرّف کے ماتحت بیٹھ گیا اور اس نے چلنے سے انکار کر دیا.تمام تاریخیں اس بات پر متفق ہیں کہ جس وقت مکہ کی طرف اس کو ہانکا گیا تو وہ بیٹھ گیا.جس طرح فوج میں سردار اور لیفٹیننٹ اور کیپٹن ہوتے ہیں اور ان کے حکم پر سپاہی حرکت کرتے ہیں اسی طرح ہاتھیوں کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے اور وہ اس سردار ہاتھی کے بغیر مقابلہ کے لئے نہیں نکلتے.اگر ان کا سردار ہاتھی کھڑا ہو جائے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر وہ حملہ کرے تو وہ بھی حملہ کرتے ہیں.بہرحال وہ اس کے تابع ہوتے ہیں اور اپنے لیڈر کے بغیر باہر نہیں نکلتے اگر نکلیں گے بھی تو بے ترتیبی کے ساتھ.بعض دفعہ وہ اس خیال سے چل پڑتے ہیں کہ شاید ہمارا سردار پیچھے آرہا ہو.مگر وہ اس کے بغیر لڑتے کبھی نہیں.جب محمود نامی ہاتھی جو تمام ہاتھیوں کا سردار تھا اچانک بیٹھ گیا تو انہیں سخت فکر ہوا کہ اگر یہ نہ اٹھا تو باقی ہاتھی بھی نہیں اٹھیں گے اور ہمارا سارا پروگرام خراب ہوجائے گا.چنانچہ اسے اٹھانے کے لئے نیزے مارے گئے.کُھرپیاں اس کے بدن میں گھسیڑی گئیں.اسی طرح دوسرے تمام آلات اور کانٹے وغیرہ اس کے پیٹ اور منہ پر مارے گئے مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا جب بہت مارتے تو وہ گھبرا کر کھڑا ہوجاتا مگر حملہ کے لئے مکہ کی طرف نہ چلتا.آخر انہوں نےاس کا منہ دوسری طرف کیا تو وہ اٹھ بیٹھا اور چل پڑا.اسی طرح وہ اس کا منہ جنوب
Page 344
کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا، شمال کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا، مشرق کی طرف کرتے تو وہ چل پڑتا مگر مکہ کی طرف منہ کرتے تو بیٹھ جاتا.یہ دیکھ کر ان پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی وہ مارتے رہے اور اسے اٹھانے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ نہ اٹھا.اس وجہ سے لشکر کے چلنے میں بہت دیر ہو گئی(جامع البیان سورۃ الفیل ).اتنے میں بادشاہ کو خبر پہنچی کہ لشکر میں بعض سپاہیوں کےجسم پر چیچک نمودار ہو گئی ہے.چیچک کی مرض حبشیوں کی مخصوص مرض ہے.بعض امراض بعض ملکوں سے مخصوص ہوتی ہیں.چیچک اصل میں حبشہ سے آئی ہے اور اسی ملک کی مخصوص بیماری ہے جس طرح آتشک اصل میں یورپ سے آئی ہے (The New Encyclopedia Britannica Under word "Syphilis") اسی لئے عربی کتب میں آتشک کو داء الافرنج کہتے ہیں یعنی یوروپین لوگوں کی بیماری.چونکہ مکہ والے خدا کے گھر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اب خدا کے گھر اور اس لشکر کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی صرف خدا ہی تھا جو اس گھر کی حفاظت کر سکتا تھا اس لئے خدا اس کام کو کرنے کے لئے آگیا.مگر چیچک کی صورت میں جو حبشیوں کے لئے سب سے زیادہ مہلک ہوتی ہے.بادشاہ کے پاس رپورٹ کی گئی کہ لشکر میں وبا پھیل گئی ہے.ہاتھی پہلے ہی اٹھ نہیں رہا تھا اس سے دلوں میں اور بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور اس دن لشکر کی روانگی کو ملتوی کرنا پڑا(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام امر الفیل و قصۃ النسأۃ).تاریخوں میں اس کے متعلق تفصیل تو نہیں آئی مگر اتنا ضرور ثابت ہے کہ اس دن لشکر ٹھہر گیا.غالباً اس لئے کہ ہاتھی نہیں چلتے تھے لیکن شام تک اور پھر دوسرے دن تک تو ہزاروں ہزار آدمی چیچک میں مبتلا ہو کر تڑپنے لگا اور دوسرے تیسرے دن ان میں موتیں بھی شروع ہو گئیں.عربوں میں اس سے پہلے چیچک کا کوئی کیس نہیں ہوا تھا اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ مرض کیا ہے.طائف کے جو لوگ ابرہہ کے لشکر کےساتھ اس لئے شامل ہو گئے تھے کہ اس طرح ان کے مندر کی عظمت بڑھ جائے گی ان میں بھی چیچک پھوٹ پڑی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ اس غداری کی سزا ہے جو انہوں نے خانۂ کعبہ کے ساتھ کی.جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں یہ مرض سخت متعدی ہے اور ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے.جو لوگ ابھی تک تندرست تھے انہیں بھی دوسرے بیماروں سے یہ مرض لگ گئی اور تمام لشکر میں ایک کھلبلی مچ گئی.نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب جو ابرہہ کے لشکر کےساتھ اس لئے آئے تھے کہ اسے رستہ دکھائیں وہ بھاگ نکلے میں بتا چکا ہوں کہ عرب اس مرض سے ناواقف تھے اور وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ چیچک کیا بلاء ہے اگر وہ اس مرض سے واقف ہوتے تو سمجھتے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے مگر چونکہ وہ اس مرض کو جانتے نہیں تھے اس لئے انہوں نے سمجھا کہ یہ خدا کا عذاب ہے اور واقعہ میں وہ عذاب ہی تھا مگر اس عذاب کی طرف مرض سے ناواقفیت کی وجہ سے ان کی توجہ بہت جلد پھر گئی اور وہ ڈر کر بھاگ گئے.
Page 345
جن قوموں میں چیچک یا ایسی ہی وبائی امراض ہوا کرتی ہیں وہ ان کے علاج بھی جانتی ہیں.حضرت عمرؓ نے اپنے زمانۂ خلافت میں جب حضرت ابوعبیدہ بن جراح کو شام کی طرف کمانڈر انچیف بنا کر بھجوایا تو وہاں طاعون پھیل گئی انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ جب طاعون ہو تو تم کیا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم پہاڑوں پر ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں.یہ سن کر بعض صحابہؓ نے کہا کہ ہمیں بھی پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے اور اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے ٹھنڈک میں یوں بھی طاعون کا اثر کم ہو جاتا ہے جب صحابہؓ اس خیال کی طرف مائل ہوئے تو حضرت ابوعبیدہ نے ان سے کہا کہ کیا تم خدا کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ اس پر ایک صحابی نے جواب دیا کہ ہم خدا کی تقدیر سے خدا کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں یعنی ہم جہاں جاتے ہیں وہاں بھی تقدیر الٰہی ہی ہو گی.اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہم تقدیر سے بھاگ رہے ہیں.چیچک کا بھی یہی علاج سمجھا جاتا ہے کہ جہاں یہ مرض ہو اس مقام کو چھوڑ دیا جائے اور ادھر ادھر کھلی جگہوں میں لوگ پھیل جائیں(The Encylopedia Britannica "Small pox").جس وقت لشکر میں چیچک پیدا ہوئی تو لشکر والوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ادھر ادھر منتشر ہو جانا چاہیے.مگر اس میں مشکل یہ پیش آگئی کہ مکہ کے اردگرد کی تمام وادیاں غیرآباد ہیں اور وہ اتنی پیچیدہ ہیں کہ میلوں میل تک جنگل پھیلتے چلے جاتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا کہ راستہ کدھر جاتا ہے.جب لشکر بھاگ کر ادھر ادھر کی وادیوں میں پھیلا تو نتیجہ یہ ہو اکہ بوجہ غیرآباد اور سخت پیچیدہ اور جنگل ہونے کے وہ راستہ بھول گئے اور چونکہ طائف کے راہنما خود بھاگ گئے تھے انہیں کوئی راستہ دکھانے والا نہ رہا اور بجائے یمن کی طرف جانے کے کوئی مدینہ کی طرف نکل گیا، کوئی نجد کی طرف چلا گیا، کوئی کسی اور علاقہ کی طرف چل پڑا.ان کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ہمارا ملک کس طرف ہے.اور بہت سے لوگ تو انہی وادیوں میں بھٹک بھٹک کر بھوکے اور پیاسے مر گئے.اسی افراتفری اور گھبراہٹ میں وہ سامان بھی جو ان کے ساتھ تھا انہوں نے وہیں پھینک دیا اور خود بے سر و سامانی کی حالت میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے.اس سے زیادہ مشکل ان کو بیماروں کے متعلق پیش آئی.انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم بیماروں کو یہیں پھینک کر چلے جاتے ہیں تو وہ کھائیں گے کہاں سے اوران کی تیمارداری کون کرے گا اور اگر ساتھ لے جاتے ہیں تو کس طرح ساتھ لے جائیں اورکہاں لے جائیں.چنانچہ کئی لوگوں نے توا پنے بیماروں کو وہیں پھینکا اور خود ادھر ادھر بھاگ گئے.اس طرح وہ بیمار بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مر گئے.اور جن لوگوں نے بیماروں کو اپنے ساتھ لیا تھا اوّل تو ان کے لئے سفر کرنا مشکل ہو گیا.پھر چونکہ یہ متعدی مرض تھا وہ خود بھی چیچک میں مبتلا ہو گئے اور اس طرح ان کا اکثر حصہ اس مرض کا شکار ہو گیا.ابرہہ بھی اس تباہی کو دیکھ کر بھاگا.وہ چونکہ بادشاہ تھا اس لئے معلوم ہوتا ہے اس نے بعض راہنما اپنے رعب
Page 346
کے ماتحت رکھے ہوئے تھے وہ سیدھا یمن کی طرف آیا مگر اس کو بھی چیچک ہو گئی اور اتنی شدید ہوئی کہ اس کے سارے بدن میں پیپ پڑ گئی اور راستہ میں اس کا گوشت جھڑتا چلا گیا.روایات میں کچھ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسے چیچک ہوئی اور شدید قسم کی ہوئی.جب وہ صنعاء پہنچا تو روایات کے مطابق اس کی صرف ہڈیاں اور سر باقی رہ گیا تھا چنانچہ وہاں پہنچ کر وہ مر گیا(مجمع البیان تفسیر سورۃ الفیل قصۃ اصحاب الفیل).یہ تباہی اس قسم کی تھی اور ایسا غیر معمولی رنگ اپنے اندر رکھتی تھی کہ اس سے ایک تہلکہ مچ گیا اور تمام لوگ انتہائی طور پر مرعوب ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ عذاب ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے.میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس بارہ میں مفسرین نے کیا کیا روایات بیان کی ہیں.یہاں صرف اس قدر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عام روایت جو مشہور ہے اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے لشکر پر اوپر سے پرندے پتھر مارتے تھے وہ پتھر ہرشخص کے سر پر پڑتے اور اس کے پاخانہ کی جگہ سے نکل جاتے(روح المعانی زیر آیت ھذا).مگر انہی روایات میں عکرمہ کی بھی ایک روایت آتی ہے جو روح المعانی میں درج ہے اور اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ مَنْ اَصَابَہُ الْـحَجَرُ جَدَرَتْہُ جس شخص پر پتھر گرتا تھا اسے چیچک نکل آتی تھی پھر وہ کہتے ہیں وَہُوَ اَوَّلُ جُدَرِیٍّ ظَھَرَ بِاَرْضِ الْعَرَبِ.یہ پہلا چیچک کا حملہ ہے جو عرب میں ظاہر ہوا اس سے پہلے عرب لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ چیچک کیا ہوتی ہے.اسی طرح طبری میں یعقوب بن عتبہ کے متعلق لکھا ہے کہ اِنَّہٗ حَدَّثَ اَنَّ اَوَّلَ مَا رُؤِیَتِ الْـحَصْبَۃُ وَالْـجُدَرِیُّ بِاَرْضِ الْعَرَبِ ذَالِکَ الْعَامَ (جامع البیان زیر آیت تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ) یعنی یعقوب بن عتبہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلا چیچک کا حملہ جو ملک عرب میں ہوا وہ اسی سال ہوا جس سال ابرہہ آیا تھا اس سے پہلے عرب میں کبھی چیچک نہیں ہوئی تھی.اب میں وہ مختلف روایات بیان کرتا ہوں جو اس بارہ میں مفسرین نے بیان کی ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو روایات میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ بھی مفسرین اور مؤرخین کی ہی بیان کردہ ہیں لیکن میںنے پہلے وہ روایات لکھی ہیں جو میرے نزدیک زیادہ درست ہیں.اب میں وہ روایات بیان کروں گا جن پر مفسرین نے اپنی تفسیر کی بنیاد رکھی ہے.روایات میں آتا ہے کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر مغمس میں حملہ کا ارادہ کیا اور اپنے ہاتھیوں کو لشکر کے آگے رکھنے کا حکم دیا تو بڑا ہاتھی جو اور تمام ہاتھیوں کا لیڈر اور سردار تھا بیٹھ گیا اور اس نے چلنےسے انکار کر دیا.اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ سمندر کی طرف سے کچھ پرندے اڑتے ہوئے آرہے ہیں.وہ پرندے چھوٹے چھوٹے تھے
Page 347
لیکن ان کے منہ آدمیوں کی طرح تھے.ان کی چونچیں اونٹوں کی طرح تھیں اور ان کے پنجے شیروں کی طرح تھے.ہر پرندہ کے پاس تین پتھر تھے.ایک پتھر اس نے چونچ میں پکڑا ہو اتھا اور ایک ایک پتھر اس نے ایک ایک پنجہ میں پکڑا ہوا تھا.پتھروں کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ چنے کے دانے سے چھوٹے اور مسور کے دانہ سے بڑے تھے گویا چنے اور مسور کے دانہ کے درمیان ان کا حجم تھا.ان پتھروں پر ابرہہ کے لشکر کے ایک ایک سپاہی کا نام لکھا ہوا تھا.کسی پر ابرہہ کا، کسی پر کسی اور کا ،کسی پر کسی اور کا.جس پتھر پر کسی کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا اسی کی طرف وہ پرندے جاتے اور اس کے سر پر وہ پتھر مارتے، پتھر اس کے سر پر لگتا اور اس کے پاخانہ کے مقام سے نکل جاتا اور وہ اسی وقت مٹی کا ڈھیر بن کر رہ جاتا.اسی طرح لکھا ہے کہ ان پتھروں سے سب کے سب آدمی مارے گئے یعنی ابرہہ کے لشکر میں جس قدر آدمی تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا سوائے ابرہہ کے.ابرہہ وہاں سے بھاگا.اس کے نام کا پتھر جس پرندے کی چونچ میں تھا وہ بھی ساتھ ساتھ اڑتا گیا لیکن وہ پتھر اس نے پھینکا نہیں یہاں تک کہ ابرہہ یمن جا پہنچا وہاں سے اس نے جہاز لیا اور اس میں سوار ہو کر حبشہ کے ساحل پر پہنچا.پھر حبشہ کے ساحل پر پہنچ کر اس زمانہ کے لحاظ سے پندرہ بیس دن کا سفر طے کرتے ہوئے وہ نجاشی کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ میں نے اس اس طرح خانۂ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ اچانک پرندے آئے اور انہوں نے آسمان پر سے پتھر پھینکے جن سے وہ سارے کے سارے آدمی مر گئے جو میرے ساتھ گئے تھے.نجاشی نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے میری عقل میں تونہیں آسکتا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے آئیں لوگوں کو پتھر ماریں اور وہ مر جائیں.اتنے میں کچھ کھٹکا ہوا اور ابرہہ نے آسمان پر ایک اسی قسم کا پرندہ دیکھ کر کہا.بادشاہ سلامت! اس قسم کے پرندے آئے تھے جن کی چونچ اور پنجوں میں پتھر تھے اور وہ ایک ایک آدمی کو مارتے تھے.ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ پرندے نے ایک پتھر ابرہہ کے سرپر پھینکا پتھر پڑنے کی دیر تھی کہ وہ مر کر زمین پر جا پڑا.یہ وہ روایت ہے جو اپنی مکمل صورت میں راویوں نے بیان کی ہے.اس روایت میں پتھروں کا ذکر آتا ہے اور اس لحاظ سے یہ میری پہلی بیان کردہ روایت کے خلاف بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے اور کوئی عقل مند اس قسم کی باتوں کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتا.جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اکثر روایتیں یہی بتاتی ہیں کہ ابرہہ وہاں سے بھاگا مگر اسے راستہ میں ہی چیچک ہو گئی اسی حالت میں وہ یمن پہنچا اور صنعاء کے قریب آکر مر گیا.اور جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جس شخص کو پتھر لگتا تھا اس کو چیچک نکل آتی تھی.دراصل یہ بہت مبالغہ آمیز روایتیں ہیں کہ پتھر ان کے سر پر پڑتے اور ان کے پاخانہ کے سوراخ سے باہر نکل جاتے.مگر اسی قسم کی روایتوں
Page 348
میں سے بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کو پتھر لگتا اس کو چیچک نکل آتی تھی.روایت کے یہ الفاظ دوسری تمام روایتوں کا بھانڈا پھوڑ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں صرف چیچک ہوئی تھی.مگر کہانی بنانے والوں نے اسے کچھ کی کچھ شکل دے دی.یہ بات صحابہ کی متواتر روایت اور بعض دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہے کہ انہیں چیچک ہو گئی تھی اور یہ بھی ثابت ہے کہ چیچک عرب میں پہلی دفعہ ابرہہ کے لشکر میں ہی نمودار ہوئی تھی.اس کے بعد ایک مسلمان کو یہ یقین کرانے کی کوشش کرنا کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لئے سمندر کی طرف سے خاص طور پر بعض ایسے جانو ربھجوا دیئے تھے جن کا دنیا میں کہیں نام و نشان بھی نہیں ملتا اور پھر یہ کہنا کہ وہ تھے تو چڑیا کے برابر مگر ان کے منہ آدمیوں کی طرح تھے چونچ اونٹ کی طرح تھی اور پنجے شیر کی طرح تھے بتاتا ہے کہ یہ کہانی بنانے والے نے الف لیلہ کے قصوں کو بھی مات کر دیا ہے اگر تو وہ یہ کہتے کہ وہ پرندے بڑے بڑے دیو معلوم ہوتے تھے جیسے خیالی اور تصوری عقاب کا نقشہ کھینچا جاتا ہے.اور بتاتے ہیں کہ ان کے منہ بڑے خونخوار اونٹوں کی طرح تھے اور انہی کی طرح ان کی گردنیں اٹھی ہوئی تھیں.شیروں کی طرح بڑے بڑے پنجے تھے اور ہر ایک پنجے اور منہ میں پچاس پچاس سیر وزنی پتھر تھے جنہیں وہ آسمان پر سے ابرہہ کے لشکر پر گراتے اور وہ اسی وقت مر جاتے.تب تو کوئی بات بھی ہوتی مگر وہ کہتے ہیںکہ وہ تھا تو چڑیا کا پنجہ لیکن نظر شیر کا پنجہ آتا تھا.بھلا چڑیا کے پنجہ سے شیر کی کیا ہیبت نظر آئے گی.پھر چڑیا کی اتنی باریک سی چونچ سے جو تراشی ہوئی پنسل کی مانند ہو وحشی اونٹ کا اثر کس طرح پڑ سکتاہے.پس یہ روایت اپنی ذات میں تمسخر سے کم نہیں اور بڑا تمسخر جو اس روایت میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پرندے پتھر پھینکتے تھے تو جسے وہ پتھر لگتا اسے چیچک نکل آتی گویا نعوذباللہ خدا کو یہ نسخہ آج کل سوجھا ہے کہ وہ انسانی جسم کے اندر سے ہی چیچک کی بیماری پیدا کر دیتا ہے اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کو یہ نسخہ معلوم نہیں تھا.اسی لئے وہ پرندے اسے پیدا کرنے پڑے جو آدمیوں کے منہ والے اور اونٹ کی گردن والے اور شیر کے پنجے والے تھے اور وہ بعض عجیب قسم کے پتھر جو اب دنیا میں نہیں ملتے پھینکتے تھے.یہ پتھر جس آدمی کے سرپر لگتے اس کے پاخانہ کے سوراخ سے نکل جاتے.مگر اس سب جدوجہد اور کوشش کا نتیجہ صرف یہ ہوتا کہ پتھر جس کو لگتا اس کو چیچک نکل آتی تھی.یہ بات اپنی ذات میں ہی بتاتی ہے کہ یہ ان پڑھ عربوں کی قوت متخیلہ تھی جس نے یہ قصہ بنایا.چونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ چیچک کیا ہوتی ہے اس لئے جب چیچک ہوئی تو لوگوں نے عجیب عجیب قصے بیان کرنے شروع کر دیئے.ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ بیان کیا ہو کہ پتھروں پر ان کی لاشیں ملیں.پھر کسی اور نے یہ ذکر کیا ہو کہ پرندوں نے ان کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے کیا ہو اتھا تو دوسرے نے یہ سمجھ لیا ہو کہ انہیں پرندوں نے ہی پتھر مار مار کر مار ڈالا تھا.پھر جب انہوں نے کسی سے سنا کہ دراصل ان کو چیچک
Page 349
نکل آئی تھی تو پہلی من گھڑت روایت کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی ملا دیا اور روایت کو اس طرح شکل دے دی کہ وہ پرندے جس کو بھی پتھر مارتے تھے اس کو چیچک نکل آتی تھی.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے مثل مشہور ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا کہ بگلا پکڑنے کی کیا ترکیب ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ بگلا پکڑنے کی ایک بڑی عمدہ ترکیب ہے.سردی کے موسم میں بگلا سُکڑا ہوا تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تم موم لو اور آہستہ آہستہ لیٹتے لیٹتے جھاڑیوں اور پتھروں کے پیچھے چھپتے بگلے کے قریب جاؤ اور اس کے سر پر موم رکھ دو.اس کے بعد چپ کر کے کسی پتھر کے پیچھے بیٹھ جاؤ.جب سورج نکلے گا اور گرمی پیدا ہو گی تو وہ موم آہستہ آہستہ پگھل کر بگلے کی آنکھوں میں جا پڑے گی اور وہ اندھا ہو جائے گا.اس وقت آگے بڑھ کر بگلے کو پکڑ لینا.اس نے کہا اتنی کوشش کرنے کی بجائے کیوں نہ میں اسی وقت بگلے کو پکڑ لوں جب میں اس کے سر پر پہنچ جاؤں موم رکھنے اور اس کے پگھلنے کا انتظار کرنے اور پھر بگلے کے اندھے ہونے تک وہیں پتھروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھے رہنے کی کیا ضرورت ہے.اس نے جواب دیا کہ اگر اس طرح پکڑ لو گے تو اس میں استادی کون سی ہو گی.بعینہٖ یہی مثال اس روایت کو بیان کرنے والوں کی ہے.وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پرندے بھجوائے ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں پتھر تھے.وہ پتھر ہر ایک کے سر پر گراتے اور پھر جس کو بھی پتھر لگتا اس کو چیچک نکل آتی.سیدھی طرح کیوں نہ کہہ دیا کہ ان کو چیچک نکل آئی تھی.یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے لئے اتنی بڑی کہانی کی ضرورت ہوتی.ہمارے سامنے خدا تعالیٰ روزانہ چیچک پیدا کرتا ہے مگر کبھی کوئی پرندے نہیں بھجواتا.فرق صرف یہی ہے کہ عرب میں چونکہ اس سے پہلے کبھی چیچک نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ سمجھ نہ سکے کہ یہ کیا چیز ہے.جیسے آتشک پہلے یورپ میں ہوئی ہے اس کے بعد وہ دوسرے ممالک میں آئی.اسی طرح ہیضہ انیسویں صدی سے پہلے یورپ میں نہیں تھا ایشیائے کوچک اور چین میں ہوتا تھا (The Encyclopedia Britanniaca Under word "Colera") پھر یہاں سےایک رَو چلی اور یورپ میں بھی ہیضہ کے واقعات ہونے لگے.اب بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں کو ہیضہ ہو گیا اگر ہم کہیں کہ خدا نے بڑے بڑے جنّ اور دیو بھیجے وہ ناک میں پھونک مارتے تھے جس سے انتڑیاں پھول جاتیں اور اس کے بعد دست لگ جاتے تھے اور آدمی مر جاتا تھا تو کیا کوئی عقلمند اس کو ماننے کے لئے تیار ہو گا؟ اسی طرح چیچک ان کو ویسے ہی نکلی جیسے آج کل لوگوں کو نکلتی ہے مگر چونکہ عربوں کو اس مرض کا علم نہیں تھا اس لئے مختلف باتوں کو سن سن کر انہوں نے ایک عجیب قصہ بنا لیا.کسی سے سنا کہ وہ پتھروں پر مرے پڑے تھے، کسی سے سنا کہ پرندے ان کا گوشت نوچتے تھے، کسی سے سنا کہ انہیں ایسے دانے نکل آئے تھے جو چنے سے چھوٹے اور مسور سے ذرا بڑے تھے.تو ان سب
Page 350
باتوں کو ملا کر انہوں نے ’’کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھان متی نے کنبہ جوڑا‘‘ کی طرح ایک افسانہ بنا لیا.حالانکہ واقعہ صرف اتنا تھا کہ ان کو چیچک نکل آئی تھی.باقی یہ کہ پتھروں کا کیا واقعہ ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں آجائے گا.بہرحال وہ بات جو میں نے بیان کی ہے اس کی تصدیق میں بعض اور روایات بھی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ چیچک والی بات ہی صحیح ہے.درمنثور میں ابن اسحاق جو ایک بہت بڑے مؤرخ گذرے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں ( یہ روایت بعض اور کتابوں میں بھی پائی جاتی ہے) کہ آپ نے فرمایا میں نے خود مکہ میں اپنی آنکھوں سے دو آدمیوں کو دیکھا جو بھیک مانگ رہے تھے اور آنکھوں سے اندھے تھے.میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو اس نے بتایا کہ یہ ابرہہ کے ہاتھیوں کے مہاوت ہیں(روح المعانی سورۃ الفیل ).دیکھ لو اس روایت سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے.چیچک ہی ایک ایسا مرض ہے جس سےا کثر لوگ اندھے ہو جاتے ہیں.پرانے زمانہ میں تو اس قسم کے اندھوں کی بڑی کثرت تھی.اگر اندھوں سے ان کے اندھا ہونے کی وجہ معلوم کی جاتی تھی تو سو میں سے اسّی کا جواب یہ ہوتا تھا کہ چیچک نکلنے کی وجہ سے وہ اندھے ہو گئے دراصل چیچک جب شدت سے نکلے تو آنکھ میں اس کے دانے نکل آتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں.اب دیکھو کہ پہلی روایت میں تو یہ ذکر تھا کہ پرندے پتھر مارتے ہر پتھر آدمی کے سر پر لگتا اور اس کے پاخانہ کے سوراخ سے نکل جاتا اور پھر اس کو چیچک ہو جاتی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان میں سے کسی بات کا ذکر نہیں فرماتیں.وہ یہ نہیں کہتیں کہ میں نے ان کے سر دیکھے تو ان میں سوراخ تھے بلکہ وہ سیدھی طرح ایک بات بیان کر دیتی ہیں کہ میں نے بعض اندھوں کو مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا تو میرے دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ ابرہہ کے ہاتھیوں کے فیلبان تھے.پھر روایت میں تو یہ ذکر آتا ہے کہ جس کو بھی پتھر لگتا وہ مر جاتا مگر حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے ان میں سے بعض لوگوں کو زندہ بھیک مانگتے دیکھا صرف اتنی بات تھی کہ اندھے ہو چکے تھے اور یہ صریح طور پر چیچک نکلنے کی علامت ہے اب بھی باوجود اس کے کہ چیچک کے ٹیکے نکل آئے ہیں اگر اندھوں سے پوچھو تو بہت سے ایسے اندھے نکل آئیں گے جن کی بینائی چیچک کے نتیجہ میں ضائع ہوئی ہو گی.اسی طرح حلیۂ ابونعیم میں آتا ہے کہ لَیْسَ کُلُّھُمْ اَصَابَہُ الْعَذَابُ یعنی ہر ایک کو یہ عذاب نہیں پہنچا تھا.اگر خدا نے پتھروں پر ہر ایک کا نام لکھ لکھ کر بھیجا تھا تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ خدا تو پتھروں پر ان کا نام لکھے مگر وہ نہ مریں.اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ بیماری تھی جس سے کچھ مر گئے اور کچھ بچ گئے.
Page 351
پھر یہ بھی تاریخوں سے پتہ لگتا ہے کہ جس کو وہ پتھر لگتا تھا اس کا گوشت جھڑنے لگ جاتا تھا.یہ بھی چیچک کی ایک علامت ہے.جب چیچک بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ نکلتی ہے تو جسم کا گوشت گل سڑ کر جھڑنے لگتا ہے اور چمڑا بالکل گل جاتا ہے.اس کے علاوہ پتھروں کی جو شکل بتائی گئی ہے وہ بھی چیچک کے دانوں سے ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر چنے سے چھوٹا اور مسور سے بڑا ہوتا تھا اور یہی چیچک کے دانوں کی کیفیت ہوتی ہے.چیچک کا دانہ چنے سے چھوٹا اور مسور سے کچھ بڑا ہوتا ہے.دراصل جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس قسم کی کہانیاں بات کو پورے طور پر نہ سمجھنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں.ہو سکتا ہے کہ کسی نے ابرہہ کے لشکر پر اس آسمانی عذاب کے نازل ہونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہو کہ خدا نے ان پر پتھراؤ کر دیا اور سننے والے نے یہ سمجھا ہو کہ واقعہ میں ان پر پتھر گرے تھے.ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں ’’تجھ پر پتھر پڑیں‘‘ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعہ میں تیرے سر پر پتھر آ آ کر گریں.میں سمجھتا ہوں ایسی ہی کوئی بات اس وقت کسی نے کہی ہو گی کہ آسمان سے ان پر پتھر پڑے.اس کا تو یہ مطلب تھا کہ آسمان سے عذاب نازل ہوا مگر سننےو الے نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ واقعہ میں ان پر پتھر پڑے تھے.پھر جب انہوں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو اس مرض کے حملہ سے بچ گیا تھا اور اس کے تمام جسم پر انہوں نےد اغ دیکھے جو چنے سے کچھ چھوٹے اور مسور سے ذرا بڑے تھے تو سمجھا کہ یہی ان پتھروں کے نشان ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر چنے سے چھوٹے اور مسور سے بڑے تھے.مجھے خود گیارہ بارہ سال کی عمر میں چیچک نکلی تھی جس کے میری کلائی پر اب تک دو نشان ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک نشان مسور سے ذرا بڑا ہے اور دوسرا چنے سے ذرا چھوٹا.مگر چونکہ عرب اس مرض کو جانتے نہیں تھے اس لئے جب انہوں نے اس کے متعلق باتیں سنیں تو قسم قسم کے قصے مشہور کرنے شروع کر دیئے اور ہمارے مفسرین نے وہی قصے اپنی تفسیروں میں درج کر لئے.حالانکہ اصل حقیقت صرف اتنی ہے کہ اصحاب فیل میں چیچک کی بیماری پھیل گئی اور وہ تتر بتر ہو گئے.بہت سے مر گئے، بہت سے اندھے ہو گئے اور کچھ بچ بھی گئے.میں نے جیسا کہ بتایا تھا یہ سارا واقعہ ایک طرف کَیْفَ کی اور دوسری طرف تَرٰى اور رَبُّکَ کی تشریح ہے قرآن کریم نے کَیْفَ کا مختصر لفظ استعمال کر کے سارے مضمون کو کھول کر رکھ دیا ہے.یعنی دیکھنا یہ نہیں کہ کیا ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہوا.یمن سے ابرہہ چلتا ہے ایک بہت بڑا لشکر ساتھ لیتا ہے.راستہ میں عرب اس کا مقابلہ کرتے ہیں مگر وہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں.تمام رستہ میں صرف تین جگہیں ایسی تھیں جہاں عربوں کے مقابلہ کا امکان تھا.ان میں سے دو جگہ لڑائی ہوئی اور عربوں کو شکست ہو گئی اور تیسری جگہ یعنی مکہ پر خود اہل مکہ نے فیصلہ کر دیا کہ ہم
Page 352
میں مقابلہ کی کوئی طاقت نہیں.غرض کوئی صورت مقابلہ کی باقی نہ رہی.لیکن ابرہہ پھر بھی ناکام ہو گیا.پس یہاں یہ سوال نہیں کہ ابرہہ کے آدمی مر گئے خدا تعالیٰ جس بات کو پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بغیر ظاہری سامانوں کے مر گئے.جتنی ظاہری طاقتیں اس کے سامنے آئیں انہوں نے شکست کھائی.یمن کے لوگوں میں بغاوت ہوئی اور وہ ابرہہ کی فوجوں سے لڑے مگر انہوں نے شکست کھائی اور ان کا سردار اور لیڈر بھی قید ہو گیا.پھر خثعم میں پہنچے تو وہاں بھی عرب قبائل نے اکٹھے ہو کر بادشاہ کا مقابلہ کیا لیکن وہاں بھی عرب مارے گئے اور ابرہہ کے مقابلہ میں زیر ہوئے.اس کے بعد جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو کنانہ اور ہذیل اور قریش نے مل کر مشورہ کیا اور وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہمارے اندر اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں.گویا جتنی انسانی تدبیریں تھیں ان کو یا تو ہیچ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا یا استعمال کرنے پر ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا.جب کوئی صور ت نہ رہی تو حضرت عبدالمطلب اپنے ساتھیوں سمیت مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے گئے اور ابرہہ کے لشکر کا انتظار کرتے رہے مگر لشکر مکہ میں داخل نہیں ہوا.جب انہوں نے آدمی بھجوا کر معلوم کیا کہ کیا بات ہے تو انہیں پتہ لگا کہ انسانی تدبیر سے نہیں بلکہ محض خدائی ہاتھ سے ان میں چیچک پھیل گئی ہے اور وہ پراگندہ ہو کر بجائے مکہ پر حملہ کرنے کے ادھر ادھر پھیل گئے ہیں اور اپنی جانیں بچانے کی فکر کر رہے ہیں.یہ سارا معاملہ کَیْفَ کی تفسیر تھا کَمْ کی تفسیر نہ تھا.ورنہ با۱۲رہ ہزار کے ایک لشکر کا مارا جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی.ابھی چین کی ایک لڑائی کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ وہاں اسی۸۰ ہزار آدمی مارا گیا اور دس لاکھ زخمی ہوا یا پکڑا گیا اتنی بڑی تعداد کے مقابلہ میں دس بارہ ہزار کے لشکر کی تباہی کی حقیقت ہی کیا رہ جاتی ہے.پھر فرق کیا ہے.تم خود ان دونوں واقعات کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دیکھ لو کہ ان میں سے کس کا اثر زیادہ ہوتا ہے.آیا چین کی لڑائی کا جس میں اسی۸۰ ہزار آدمی مارا گیا ہے یا اس کا جس میں صرف بارہ ہزار آدمی شامل ہوا تھا مگر جب حملے کا وقت آیا تو اس میں ایک ایسی بیماری پھوٹ پڑی جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا.یقیناً ہر شخص اس سے متاثر ہو گا.اس لئے نہیں کہ دس یا بارہ ہزار آدمی مرے بلکہ اگر صرف بارہ آدمی مکہ پر حملہ کرتے اور فرض کرو کہ مکہ میں صرف حضرت اسمٰعیل علیہ السلام ہوتے اور یہ واقعہ پیش آجاتا تو جو اثر اس واقعہ کا طبیعت پر پڑتا اور جس طرح اس سے خدا تعالیٰ کی خدائی کا انکشاف ہوتا وہ با۱۲رہ لاکھ کے مرنے سے بھی نہ ہوتا.اگر با۱۲رہ لاکھ انسان انسانی تدبیر سے مر جائے تو بہرحال یہی کہا جائے گا کہ وہ انسانی تدبیر سے مرا.اور انسانی تدبیروں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک غالب آتا ہے اور دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے.لیکن اگر با۱۲رہ آدمی بھی خدائی ہاتھ سے مریں تو اس سے ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی قوت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے جو طبائع پر اثر کئے بغیر نہیں
Page 353
رہتا.اسی لئے خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اَلَمْ تَرَ مَا فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ یا کَمْ عَذَّبَ کا لفظ اس نے استعمال نہیں بلکہ اس نے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ کے الفاظ استعمال کئے ہیں یعنی ہم نے کس طرح ایک ایسی تدبیر ان کو ہلاک کرنے کے لئے کی جس میں انسانی ہاتھ کا کوئی دخل نہیں تھا.چیچک ایسی ہی مرض ہے جو کسی انسان کے قبضہ میں نہیں.بعض مرضیں بےشک ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو پھیلایا جا سکتاہے جیسے ہیضہ ہے یا ٹائیفائڈ ہے یا طاعون ہے.گو ان کے پھیلانے میں بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں لیکن چیچک کے متعلق اب تک کوئی ایسا طریق معلوم نہیں ہو سکا جس سے اسے لوگوں میں پھیلایا جا سکے اور ہیضہ اور ٹائیفائڈ اور طاعون کے متعلق بھی موجودہ زمانہ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ امراض پھیلائی جا سکتی ہیں.(Encylopedian Britannia Under word "Cholera, typhoid, plague") اس سے پہلے ان امراض کے متعلق لوگوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ یہ پھیلائی جا سکتی ہیں.پس آج سے چودہ سو سال پہلے ابرہہ کے لشکر میں ایک ایسی بیماری کا پھیل جانا جو کبھی عرب میں نہ ہوئی تھی اور جس کا عربوں کو پتہ تک نہیں تھا.اس کا علاج جاننا تو الگ رہا یقینی طور پر بتاتا ہے کہ یہ بیماری خدا نے پیدا کی تھی اسی لئے كَيْفَ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ.اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے کس طرح کیا.’’تیرے رب‘‘ کے الفاظ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ ان الفاظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ فعل محض تیری خاطر کیا گیا تھا.جب ماں اپنے بچہ سے کہتی ہے کہ ’’تیری ماں نے کیا کیا‘‘ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تیری خاطر کیا کِیا.اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دیکھ کہ ہم نے تیری خاطر کس طرح اپنی قدرت کا نشان دکھایا.تو بارہ ہزار کی موت نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ کیا کوئی انسان تھا جس نے ان کو مارا.کیا کوئی انسانی تدبیر تھی جس نے ان کا خاتمہ کیا.جب تمام حیلے بےکار ہو گئے، جب تمام کوششیں جاتی رہیں تو وہ خدا جو تجھ کو مکہ میں پیدا کرنا چاہتا تھا، وہ خدا جو تجھ کو دنیا کا سردار بنانا چاہتا تھا، وہ خدا جو تجھ کو مکہ میں بہت بڑی عظمت دینا چاہتا تھا اس نے اپنی قدرت کا زبردست ہاتھ دکھایا.پس اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! تو دیکھ کہ کس طرح ہم نے ان میں بیماری پیدا کر کے تمام لشکر کو تباہ کر دیا.اور جب انسان ناکام و نامراد ہو کر بھاگ گیا تو اس لشکر کے راستہ میں ہم خود کھڑے ہو گئے.غرض کَیْفَ اور تَرٰى اور رَبُّکَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس واقعہ کے اندر ایسے امور پائے جاتے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ سب واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہوا.اوّل دو ہزار سال سے اوپر گذر گئے مگر مکہ پر کوئی حملہ نہ ہوا لیکن اس سال جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 354
پیدا ہونے والے تھے دشمن کےد ل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ مکہ پر حملہ کرے اور خانۂ کعبہ کو گرا دے.اس کا موجب چاہے یہ سمجھ لو کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور عربوں میں یہ تحریک شروع ہو گئی تھی کہ وہ موعود جس کی انبیاء کے نوشتوں میں ایک لمبے عرصہ سے خبر چلی آرہی ہے عنقریب ظاہر ہونےو الا ہے اور عیسائی ڈرتے تھے کہ اگر وہ موعود عرب میں ظاہر ہو گیا جیسا کہ بعض پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ عرب میں ظاہر ہو گا تو ان کے لئے سخت مشکلات پیدا ہو جائیں گی.اس لئے انہوں نے چاہا کہ عرب جس نقطۂ مرکزی پر متحد ہیں اسے گرا دیا جائے اور اس طرح ان کی طاقت کو توڑ دیا جائے.اور چاہے یہ سمجھ لو کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اس کا سر کچلنے والا ایک زبردست انسان دنیا میں کھڑا ہونے والا ہے تو اس نے کوشش کی کہ وہ حربہ جو اس کے خلاف استعمال کیا جانے والا ہے بے کار ہو جائے ان دونوں میں سے کوئی وجہ سمجھ لو بہرحال یہ حملہ اتفاق نہیں تھا.آخر یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر خانۂ کعبہ پر کسی کی طرف سے حملہ ہونا تھا تو بناءِ کعبہ کے بعد پہلے سال کیوں نہ ہوا، دوسرے سال کیوں نہ ہوا، تیسرے سال کیوں نہ ہوا، چوتھے سال کیوں نہ ہوا، پانچویں سال کیوں نہ ہوا، چھٹے سال کیوں نہ ہوا؟ یا اگر کسی نے حملہ کرنا ہی تھا تو پہلی صدی میں کیوں نہ کیا، دوسری صدی میں کیوں نہ کیا، تیسری صدی میں کیوں نہ کیا؟ بائیس سو سال تک برابر خاموشی چلی گئی.لیکن ادھر وہ شخص پیدا ہوتا ہے جس کے پیدا ہونے کی خبر خانۂ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت دی گئی تھی جس نے ساری دنیا کو اپنے مذہب سے روشناس کرنا تھا اور جس نے تمام قوموں کا مرجع بننا تھا.اور ادھر خانۂ کعبہ کو تباہ کرنے کے لئے ایک لشکر آجاتا ہے.صاف پتہ لگتا ہے کہ خواہ یہ تدبیر انسانی دماغ سے پیدا کی گئی ہو خواہ شیطانی دماغ نے اس کو پیدا کیا ہو بہرحال یہ تھی اسی موعود کی طاقت توڑنے کے لئے.دوم اللہ تعالیٰ نے صرف حملہ آور دشمن کو نہیں مارا بلکہ اس کی حکومت کو ہی مٹا دیا.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَبْرَھَہ بلکہ فرمایا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ یعنی وہ قوم جو فیل والی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا.کیونکہ اس حکومت سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ وہ آئندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ میں روک نہ بنے.یمن اور مکہ کا آپس میں گہرا تعلق تھا اگر یمن میں مسیحی حکومت رہتی اور صرف ابرہہ کا لشکر تباہ ہو جاتا تو ممکن تھا کہ اس کے بعد اور لشکر آتے اور مکہ پر حملہ کرتے اور اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں روک پیدا ہوتی.پس خدا تعالیٰ نے اس فتنہ کا استیصال کرنے کے لئے اس حکومت کو ہی مٹا دیا جس سے یہ خطرہ ہو سکتا تھا.غرض یہ تباہی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سوچی سمجھی ہوئی تدبیر تھی.آنے والے موعود کا راستہ صاف کرنے کے لئے.اگر مکہ کے لوگ اس وقت لڑتے تو خدا تعالیٰ میں یہ بھی طاقت تھی کہ وہ مکہ والوں کو ابرہہ اور اس
Page 355
کے لشکر پر غالب کر دیتا.قرآن کریم میں صاف طور پر آتا ہے کہ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ(البقرۃ :۲۵۰) بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی طاقتوں پر غالب آجاتی ہیں.بدر میں ایسا ہی ہوا.غزوہ خندق میں ایسا ہی ہوا.مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو اپنے سے کئی گنا بڑی جماعت پر غالب آگئی.لیکن بدر نے مکہ والوں کو ایسا ڈرایا نہیں کہ وہ مسلمانوں پر دوسرا حملہ نہ کریں.وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی جماعت ہم پر غالب تو آئی ہے مگر اس میں کوئی عجیب بات نہیں.کبھی ایک آدمی تین پر بھی غالب آجاتا ہے بلکہ دنیا میں اس قسم کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک دس پر غالب آگیا یا ایک بیس پر غالب آگیا.پس بدر میں مسلمانوں کے غلبہ کے باوجود کفار ڈرے نہیں.لیکن کعبہ پر حملہ آور ہونے والوں کی تباہی کا واقعہ خدا نے بغیر کسی انسانی ہاتھ اور تدبیر کے اس لئے ظاہر کیا تاکہ لوگ ڈر جائیں اور وہ یقین کر لیں کہ اس واقعہ میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے.پس اس موقعہ پر خدا تعالیٰ نے بھی ایک سوچی ہوئی تدبیر اختیار کی جیسے انسان نے بھی ایک سوچی ہوئی تدبیر اختیار کی تھی.ایک انسان نے ایک گرجا بنایا مگر اس لئے نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے بلکہ اس لئے کہ عربوں کی توجہ خانۂ کعبہ کی طرف سے ہٹا کر اس کی طرف مبذول کرا دے.پھر عربوں میں منادی کی گئی اور خاص طور پر وہ عرب رؤوسا چنے گئے جن کا پبلک پر اثر تھا اور ان کو انعام و اکرام کے وعدے دے کر اس غرض کے لئے مقرر کیا گیا کہ وہ لوگوں میں یہ پراپیگنڈہ کریں کہ آئندہ خانۂ کعبہ کی بجائے اس گرجے کا حج کیا جائے حالانکہ حج گرجوں کانہیں ہوا کرتا.اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہاں اصل مقصد گرجے کا قیام نہ تھا بلکہ خانۂ کعبہ کے مقام کو گرانا مقصود تھا.اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کی اصل غرض ابرہہ کو مارنے کی نہیں تھی بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ سے ہر قسم کی روکوں کو دور کرنا تھی.پھر جس طرح مکہ پر حملہ اتفاقی نہیں ہوا اسی طرح ابرہہ کی تباہی بھی اتفاقی نہیں ہوئی.اس کی غرض بھی یہی تھی کہ عرب کے نبی کے لئے ترقی کے امکانات بالکل مٹا دیئے جائیں.اور خدا تعالیٰ کی غرض بھی یہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے لئے یمن کی حکومت بالکل مٹا دی جائے تاکہ آپ ہر قسم کے خطرہ میں آئے بغیر ترقی کر سکیں.اصل بات یہ ہے کہ زمانۂ محمدی کے متعلق جو پیشگوئیاں سابق کتب میں پائی جاتی تھیں ان کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے تھے.مسیحیوں نے ان پیشگوئیوں کو یا تو بائبل سےا خذ کیا تھا یا ان کے اولیاء نے جو پیشگوئیاں کی تھیں ان سے انہوں نے یہ نتائج اخذ کئے تھے.بائبل کی پیشگوئیاں توبالکل واضح ہیں جیسے استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ’’میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا.‘‘ (استثناء باب ۱۸آیت ۱۸) دوسری جگہ اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا.
Page 356
(استثناء باب ۱۸ آیت ۱۵)صاف بات ہے کہ جب بنو اسحاق کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی آئے گا تو اس سے مراد بنو اسمٰعیل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا.جیسے اگر سیدوں کو یہ کہا جائے کہ ’’تمہاری بھائی قوم میں سے‘‘ تو اس سے سید مراد نہیں ہو سکتے یا پٹھانوں کو یہ کہا جائے کہ ’’تمہاری بھائی قوم میں سے‘‘ تو اس سے پٹھان مراد نہیں ہو سکتے یا مغلوں کو یہ کہا جائے کہ ’’تمہاری بھائی قوم میں سے‘‘ تو اس سے مغل مراد نہیں ہو سکتے.بہرحال کوئی دوسری قوم مراد ہو گی.اسی طرح ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے معروف قبائل یا بنواسحاق تھے یا بنو اسماعیل، جب بنو اسحاق کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی کھڑا کیا جائے گا جو موسیٰ کی مانند ہو گا.جیسا کہ استثناء میں یہ پیشگوئی موجود ہے تو اس کے صاف معنے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی زمانہ میں بنو اسماعیل میں نبی کھڑا کرے گا.اور تورات سے پتہ چلتا ہے کہ بنو اسماعیل عرب میں جا کر بسے ہیں.اس کے متعلق بائبل کے بہت سے حوالے ہیں.یسعیاہ نبی کی کتاب میں بھی جہاں وہ عرب کے متعلق پیشگوئی کرتے ہیں بنو اسمٰعیل کا خاص طور پر نام آتا ہے گویا یسعیاہ نبی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بنو اسمٰعیل عرب میں بسے ہوئے تھے.غرض ایک طرف بائبل یہ بتاتی ہے کہ بنو اسمٰعیل عرب میں تھے اور دوسری طرف بائبل یہ پیشگوئی کرتی ہے کہ بنو اسحاق کے بھائیوں یعنی بنو اسمٰعیل میں سے ایک نبی آئے گا.ان دونوں پیشگوئیوں کو ملا کر یا پیشگوئی کے دونوں گروپوں کو ملاکر صاف طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک نبی بنو اسماعیل میں آنےو الا تھا.پس جب اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا وقت قریب آگیا تو لوگوں میں اس آنے والے موعود کے متعلق ایک عام چرچا شروع ہو گیا.اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق گذشتہ اولیاء نے بھی بہت سی پیشگوئیاں کی ہوئی تھیں اور لوگ ان کا علم رکھتے تھے.درحقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ عظیم الشان پیشگوئیاں جہاں انبیاء سے کراتا ہےو ہاں انبیاء کے بعد آنے والے اولیاء سے بھی ان کے متعلق کئی قسم کی پیشگوئیاں کرادیتا ہے اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں یہودی کتب میں ایسی پائی جاتی ہیں جو بائبل میں نہیں اور جو درحقیقت یہود کے اولیاء نے کی تھیں.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بھی بیسیوں پیشگوئیاں ایسی ہیں جو امت محمدیہ کے اولیاء نے کی ہیں.اہم اور بنیادی پیشگوئیاں تو انبیاء کے ذریعہ ہی ہوتی ہیں لیکن بعض چھوٹی چھوٹی کیفیتیں اللہ تعالیٰ اولیاء کے ذریعہ بھی بیان کر دیتا ہے اور اس طرح تمام دنیا مختلف پیشگوئیوں کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے موعود کا انتظار کرنے لگتی ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آگیا تو الٰہی سنت کے مطابق عام طبائع میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اب کوئی ظہور ہونے والا ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قریب زمانہ
Page 357
میں لوگوں میں ایک عام حرکت پیدا ہو گئی تھی اور عیسائی مسیحؑ کا اور مسلمان مہدی کااور دوسری قومیں اپنے اپنے موعود کا انتظار کرنے لگ گئی تھیں.چونکہ عیسائیوں کو بائبل اور اولیاء کی پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ نبی عرب میں پیدا ہوگا اس لئے ان میں گھبراہٹ تھی کہ اب ایک شدید حملہ مسیحیت پر ہونے والا ہے.چنانچہ بخاری اور دوسری کتب احادیث میں صاف لکھا ہے کہ قیصرِ روما اس وقت ستاروں کو دیکھا کرتا تھا تا اسے معلوم ہو کہ مختون نبی (یعنی عرب) کب پیدا ہو گا.اس بارہ میں جو حدیث آتی ہے اس میں لکھا ہے کہ قیصر روما شام میں تھا کہ اس نے ایک دن ستاروں کو دیکھا اور کہا ان ستاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کی خبر کتابوں میں دی گئی ہے وہ عنقریب ظاہر ہونےو الا ہے.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط اسے پہنچا تو ابوسفیان ان دنوں وہیں تھا وہ خود کہتا ہے کہ قیصرِ روما نے مجھے بلایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات مجھ سے پوچھے اور پھر اس نے اپنی قوم سے کہا مجھے تو یہ وہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کی خبر ہماری پیشگوئیوں میں پائی جاتی ہے.اسی طرح حدیثوں میںآتا ہے کہ اس نے ایک دن ستاروں میں دیکھا اور کہا کہ نبیٔ مختون عنقریب ظاہر ہونے والا ہے(بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی ).میں سمجھتا ہوں جب قیصرِ روما نے ستاروں کو دیکھ کر یہ بات کہی تو ابوسفیان نے اپنے زمانہ کے خیالات کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ جیسے نجومی پیشگوئی کرتے ہیں اسی طرح قیصرِ روما نے ستاروں کو دیکھ کر یہ بات کہی ہے.حالانکہ نہ اس قسم کے نجومی دنیا میں ہوتے ہیں اور نہ وہ پیشگوئیاں کرتے ہیں.یہ ساری بات ہی غلط ہے اصل بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عظیم الشان خبریں جو نبیوں کے متعلق ہوتی ہیں ان میں آنے والے نبی کی علامت کے طور پر بعض ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں جوستاروں اور سیاروں سے تعلق رکھتی ہیں.جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی دو علامتیں ایسی ہیںکہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ دو علامتیں کسی مدعی کی تصدیق کے لئے ظاہر نہیں ہوئیں.اور وہ یہ کہ رمضان کے مہینہ میں چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی رات اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے دوسری تاریخ گرہن لگے گا (دارقطنی کتاب العیدین باب صفۃ صلوٰۃ الخسوف والـکسوف وھیئتمھا) اب اگر کوئی شخص سورج اور چاند کو گرہن لگتے دیکھ کر یہ کہے کہ میں نے سورج اور چاند کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے کہ مہدویت کا مدعی ظاہر ہو گیا ہے یا عنقریب ظاہر ہونے والا ہے تو کیا کوئی شخص اس کا یہ مطلب لے گا کہ اس نے سورج اور چاند کی شکل دیکھ کر یہ اندازہ لگایا ہے یا سورج اور چاند کی حرکتوں سے اس نے یہ پیشگوئی معلوم کی ہے.وہ کہے گا یہی کہ میں نے سورج اور چاند کو دیکھ کر یہ سمجھا ہے.مگر اس کی مراد یہ ہو گی کہ سورج اور چاند کے متعلق جو پیشگوئی تھی اس کو پورا ہوتے دیکھ کر میں نے یہ سمجھا
Page 358
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موعود آنےو الا ہے اسی طرح قیصرِ روما کے قول کا یہ مطلب نہیں کہ نجومی کی طرح اس نے ستاروں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ عرب کا نبی ظاہر ہونے والا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں ستاروں کے متعلق پہلی کتب میں کوئی خاص پیشگوئی ہو گی جو ان کے اولیاء نے کی ہو گی اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ثبوت ہو گی.جب قیصر روما نے اس علامت کو ستاروں میں پورا ہوتے دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ نبیٔ مختون کے ظہور کا وقت اب قریب آگیا ہے.ہماری جماعت کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مخالف مولوی جو غالباً گجرات کا رہنے والا تھا ہمیشہ لوگوں سے کہتا رہتا تھا کہ مرزا صاحب کے دعویٰ سے بالکل دھوکا نہ کھانا حدیثوں میں صاف لکھا ہے کہ مہدی کی علامت یہ ہے کہ اس کے زمانہ میں سورج اور چاند کو رمضان کے مہینہ میں گرہن لگے گا.جب تک یہ پیشگوئی پوری نہ ہو اور سورج اور چاند کو رمضان کے مہینہ میں گرہن نہ لگے ان کے دعویٰ کو ہرگز سچا نہیں سمجھا جا سکتا.اتفاق کی بات ہے وہ ابھی زندہ ہی تھا کہ سورج اور چاند کے گرہن کی پیشگوئی پوری ہو گئی.اس کے ہمسائے میں ایک احمدی رہتا تھا اس نے سنایا کہ جب سورج کو گرہن لگا تو اس نے گھبراہٹ میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر ٹہلنا شروع کر دیا.وہ ٹہلتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ’’ہن لوگ گمراہ ہون گے‘‘ ’’ہن لوگ گمراہ ہون گے‘‘ یعنی اب لوگ گمراہ ہو جائیں گے.اس نے یہ نہ سمجھا کہ جب پیشگوئی پوری ہو گئی ہے تو لوگ حضرت مرزا صاحب کو مان کر ہدایت پائیں گے گمراہ نہیں ہوں گے.عیسائی بھی ایک طرف تو یہ مانتے تھےکہ وہ تمام علامتیں پوری ہو گئی ہیں جو پہلی کتب میں پائی جاتی ہیں مگر دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سن کر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اس وقت اتفاقی طور پر ایک جھوٹے نے دعویٰ کر دیا ہے جیسے مسلمان کہتے ہیں علامتیں تو پوری ہو گئی ہیں مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جھوٹے نے دعویٰ کر دیا ہے.مگر عجیب بات یہ ہے کہ ایسا اتفاق ایک جھوٹے کو ہی نصیب ہوتا ہے سچے کو نصیب نہیں ہوتا.غرض میرے نزدیک پہلی کتابوں میں اس قسم کی پیشگوئی پائی جاتی تھی کہ فلاں ستارہ جب فلاں جگہ پر ہو گا یا فلاں علامت تمہیں ستاروں میں دکھائی دے گی تو یہ اس بات کا نشان ہو گا کہ وہ نبی جس کی خبر دی جارہی ہے عنقریب ظاہر ہونے والا ہے.قیصر نے ایسی ہی کوئی علامت دیکھ کر یہ بات کہی لیکن سننےو الے چونکہ اصل حقیقت سے آگاہ نہیں تھے اس لئے جب اس نے یہ کہا کہ میں نے ستاروں میں نبیٔ مختون کی علامت دیکھ لی ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جس طرح نجومی ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں اسی طرح اس نے ستاروں کو دیکھ کر کوئی بات معلوم کی ہے.اسی طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عرب لوگ محمد نام نہیں رکھتے تھے مگر جب آنے والے موعود کے متعلق
Page 359
عام چرچا شروع ہوا تو انہوں نےا پنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل کی پیشگوئیوں سے یہ سمجھا گیا تھا کہ نبی ٔ عرب محمد نامی ہو گا.پس قربِ زمانۂ نبوی میں جب عربوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ آنے والا آرہا ہے تو انہوںنے تفاؤل کے طور پر اپنے بچوں کےنام محمد رکھنے شروع کر دیئے.اس سے ظاہر ہے کہ اس وقت یہ عام احساس پیدا ہو رہا تھا کہ نبیٔ عربی کا زمانہ قریب آگیا ہے.پھر لوگوں کے اس عام احساس کا اس امر سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہودی لوگ شام کو چھوڑ کر مدینہ اور خیبر میں آبسے تھے کیونکہ ان کے اولیاء نے انہیں یہ خبر یں دے رکھی تھیں کہ اب وہ ’’نبی‘‘ ظاہر ہونے والا ہے لیکن ظاہر جنوبی علاقہ میں ہو گا(وفاء الوفاء الـجزء الاوّل صفحہ ۱۶۰) گویا وہ اس کا علاقہ مدینہ اور اس کا ماحول بتاتے تھے اور اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے کہ تم اس طرف کو چلے جاؤ تاکہ جب وہ نبی مبعوث ہو تو اس کی برکت سے تم عیسائیوں کے ظلموں سے بچ جاؤ.ان میں یہ خبر تھی کہ اگر وہ اس موعود کو مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کر دے گا بعض یہودیوں کی نسبت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ مدینہ اور اس کے نواح میں اس لئے آکر بسے تھے کہ وہ نبی اس علاقہ میں ظاہر ہونے والا ہے اور اس سے قیاس ہوتا ہے کہ یہ عرب کی طرف ہجرت کی رَو اور مدینہ کے قریب یہود کا بستیاں بنانا الٰہی پیشگوئیوں کی وجہ سے تھا.یہ ساری باتیں جن کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے بتاتی ہیں کہ عیسائیوں اور یہود دونوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا قیصرِ روما نے آسمان پر ایسی علامتیں دیکھیں جن کو دیکھ کر اسے کہنا پڑا کہ نبی ٔ مختون کے ظہور کا وقت آگیا ہے.یہودی اس لئے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے کہ ان کے اولیاء نے یہ بتایا تھا کہ وہ نبی اس علاقہ میں ظاہر ہونےو الا ہے اور عربوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس لئے اپنے بچوں کانام محمد رکھنا شروع کر دیا جو پہلے نہیں ہوتا تھا کہ شاید انہی کا بچہ وہ خوش قسمت بچہ ہو جس نے دنیا کا نجات دہندہ بننا ہے.یہ تینوں باتیں بتاتی ہیں کہ عربوں میں بھی یہ احساس تھا کہ اس نبی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا ہے.یہود میں بھی یہ احساس تھا کہ اس نبی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا ہے اور عیسائیوں میں بھی یہ احساس تھا کہ اس نبی کے پیدا ہونے کا وقت آگیا ہے.لیکن یہودیوں اور مسیحیوں یا یوں کہو کہ ان میں سےا کثر کا یہ خیال تھا کہ وہ ہوگا ان کی قوم میںسے گو ظاہر ہو گا عرب سے.وہ یہ تو سمجھتے تھے کہ علامتیں بالکل ظاہر ہیں مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ نبی ہم میں سے ظاہر ہو گا کسی اور قوم میں سے نہیں ہو گا.عرب سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہو گا، عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہوگا، یہودی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے ہو گا.
Page 360
غرض ان میں یہ تو چرچا تھا کہ وہ موعود جس کی خبر دی گئی تھی آنےوالا ہے مگر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا کسی اور قوم میں سے نہیں آئے گا.یہودی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا اور عیسائی سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا اور چونکہ آنے والے کی خبریں ہر قوم میں پائی جاتی تھیں اس لئے ان کے دلوں میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ان پیشگوئیوں سے کوئی اور قوم ’’ناجائز فائدہ‘‘ نہ اٹھالے.اور چونکہ مسیحی دنیا کے بادشاہ تھے وہ سیاسی طور پر اس خیال کے تقویت پانے کو اپنے خلاف سمجھتے تھے.اس لئے ان میں سے بعض صاحبِ اقتدار لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بہتر ہو کہ عربوں کے شیرازہ کو بکھیر دیا جائے تاکہ نبیٔ عربی کے خیال کے ماتحت یہ ایک مرکز پر جمع نہ ہو جائیں اور مسیحیت کے لئے مشکلات پیش نہ آئیں.چنانچہ انہی باتوں کے نتیجہ میں ابرہہ نے پہلے گرجا بنایا پھر اسے رشوتوں سے عربوں میں مقبول کرنا چاہا اور جب اس میں اسے کامیابی نہ ہوئی تو خانۂ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کیا.لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نشان دکھایا اس نے بجائے آپؐکا رستہ روکنے کے اس کو اور بھی کھلا کر دیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ ہے جس کے لئے اس خانۂ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کا مخالف ہے جو اس گھر کو تباہ کرنا چاہتا ہے.کیونکہ وہ اس گھر کو نہیں مٹاتا بلکہ اس مقصود پر حملہ کرتا ہے جس کے لئے اس گھر کو بنایا گیا تھا.لطیفہ یہ ہے کہ وہی قوم جس نے اس نبی کو گرانے کی کوشش کی تھی اسی قوم کے پروں کے نیچے نبی عربی کی جماعت نے پناہ حاصل کی.یمن حبشہ کا صوبہ تھا اور یمن کا گورنر نجاشی کے ماتحت تھا یہ نجاشی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک زندہ رہا.اس نجاشی کی فوج کسی زمانہ میں مکہ پر حملہ آور ہوئی کہ وہ خانۂ کعبہ کو گرائے.اس لئے آئی کہ یہ نقطۂ مرکزی نہ رہے تاکہ اگر عرب میں کوئی مدعیٔ نبوت کھڑا بھی ہو تو اسے خانۂ کعبہ سے طاقت حاصل نہ ہو.مگر اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں جوان ہوئے اور مکہ میں ہی ادھیڑ عمر کو پہنچے مگر جب چالیس سال کے بعد آپؐنے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو مکہ کے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور رفتہ رفتہ یہ مخالفت اتنی ترقی کر گئی کہ دعویٰ نبوت کے پانچویں سال مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آکر آپ کی قوم پناہ لینے کے لئے ایک غیرملک کی طرف ہجرت کر گئی اور وہ ملک اسی نجاشی کا ملک تھا جس کے لشکر نے نبی عربی کی طاقت توڑنے کے لئے مکہ پر حملہ کیا تھا.مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے حبشہ پہنچے تاکہ نجاشی کو کہہ کر وہ ان لوگوں کو مکہ میں واپس لائیں اور ان پر اپنے مظالم کا سلسلہ جاری رکھیں.خدا کی قدرت ہے وہ مکہ والے جو ابرہہ کا خانۂ کعبہ پر حملہ برداشت نہ کر سکتے تھے اور جو ابرہہ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندرنہ پاکر پہاڑوں پر چلے گئے تھے وہ ابرہہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس اس لئے جاتے ہیں کہ اس شخص کی جماعت کو مارا جائے جس کے لئے خانۂ کعبہ کی
Page 361
بنیاد رکھی گئی تھی.مگر وہ نجاشی جس کا لشکر اس لئے آیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا نہ ہوں وہ آپ کی مدد کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے گویا مارنے والا بچانے والا بن جاتا ہے اور بچانے والا مارنے والا بن جاتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ جب مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور قریش کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے دو سرداروں کو جن میں سےایک حضرت عمرو بن العاص بھی تھے جو بعد میں اسلام لے آئے اور دوسرے عبداللہ بن ربیعہ تھے حبشہ بھجوایا تاکہ نجاشی سے مل کر ان لوگوں کو مکہ میں واپس لایا جائے.وہ اپنے ساتھ بہت کچھ تحائف لے کر حبشہ پہنچے اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آگئے ہیں آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھجوا دیں.نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے.انہوں نے کہا اے بادشاہ! ہم ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا تھے.دن رات شرابیں پیتے اور ہر قسم کے گھناؤنے اور ناجائز کاموں میں مبتلا رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول ہم میں مبعوث فرمایا اور ہم اس پر ایمان لے آئے.اس پر ایمان لانے کی برکت سے اب ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، فسق و فجور سے بچتے ہیں، ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں، نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی مفید کاموں میں صرف کریں.مگر ہماری قوم کے افراد کو ہم سے اختلاف ہے اور وہ اس کی وجہ سے ہم پر ہر قسم کے مظالم کرتی ہے.ہم نے جب اس کے مظالم کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم تیرے ملک میں پناہ لینے کے لئے آگئے.اے بادشاہ! ہم نے سنا ہے کہ تو بڑا منصف ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے متعلق انصاف سے کام لیا جائے اور ہمیں ہماری قوم کے حوالے نہ کیا جائے.بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ میرے ملک میں بڑی خوشی سے رہ سکتے ہیں اور اس نے قریش کو جواب دے دیا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے ساتھ روانہ نہیں کر سکتا.دوسرے دن انہوں نے پادریوں کو اکسایا اور کہا کہ یہ مسلمان تمہارے مسیحؑ کو گالیاں دیتے ہیں انہوں نے دربار میں شور مچا دیا کہ آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ کیسے دیا یہ تو ہمارے دین کے سخت مخالف ہیں ان کو اپنے ملک میں ہرگز پناہ نہیں دینی چاہیے.بادشاہ نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ مسیحؑ اور ان کی والدہ حضرت مریم صدیقہ کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا مسیحؑ کو ہم نبی سمجھتے ہیں اور حضرت مریم کو صدیقہ سمجھتے ہیں.چنانچہ انہوں نے سورۂ مریم کی کچھ آیتیں بھی پڑھ کر سنائیں جن میں ان عقائد کا ذکر آتا ہے.بادشاہ نے کہا یہ باتیں تو ٹھیک ہیں.نجاشی دراصل مؤحد تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک نشان اپنے زمانۂ بچپن میں دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ مؤحد ہو گیا تھا.آج تک بھی عیسائیوں میں ایک مؤحد فرقہ پایا جاتا ہے.وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ سب سے بڑے نبی ہیں مگر
Page 362
بہرحال وہ آپ کو نبی ہی سمجھتے ہیں خدا نہیں سمجھتے(جیوش انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ Unitarianism ).جب نجاشی نے کہا کہ مسلمان ٹھیک کہتے ہیں تو اس کی قوم نے شور مچا دیا کہ ٹھیک کس طرح ہے مسیحؑ اور اس کی والدہ حضرت مریم کو تو خدائی طاقتیں حاصل تھیں.اس وقت اس نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک تنکا اٹھایا اور اسے اٹھا کر کہا خدا کی قسم مسیحؑ کا جو درجہ ان مسلمانوں نے بیان کیا ہے میں ایک تنکے کے برابر بھی مسیح کو اس سے زیادہ نہیں سمجھتا.اگر تم لوگ خفا ہوتے ہو تو بے شک ہو جاؤ مجھے تمہاری پروا نہیں.میں ابھی بچہ تھا کہ تم نے مجھ سے غداری کی مگر میرے خدا نے اس وقت مجھے تخت دیا اور تمہیں میرے مقابلہ میں ناکام و نامراد رکھا.جس خدا نے مجھے اس وقت تخت دیا تھا جب میں بچہ تھا اس خدا سے میں اب بڑھاپے میں غداری نہیں کر سکتا اور مسیحؑ کو کوئی ایسا درجہ نہیں دے سکتا جو حقیقت کے خلاف ہو.جس واقعہ کی طرف نجاشی نے اشارہ کیا وہ یہ تھا کہ ابھی یہ چھ سات سال کی عمر کا ہی تھا کہ اس کا باپ مر گیا اور اس کا چچا سلطنت کا سربراہ ہو کر کام کرنے لگا کچھ عرصہ کے بعد اس نے یہ دیکھ کر کہ میرا بھتیجا ابھی بہت چھوٹا ہے اور اس کے جوان ہونے میں دیر لگے گی پادریوں اور امراء کو بلا کر کہا کہ اس بچہ کے جوان ہونے تک تو ملک کی حالت بہت کمزور ہو جائے گی اگر تم لوگ مناسب سمجھو تو میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دوں.چونکہ اس وقت وہی برسراقتدار تھا اور نجاشی بہت چھوٹا تھا انہوں نے اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا.ایک دن درباریوں میں سے کسی نے اپنے گھر میں یہ بات کی جو اس کے لڑکے نے بھی سن لی اور چونکہ لڑکے لڑکوں کےد وست ہوتے ہیں اس نے یہ بات نجاشی کو آکر سنا دی کہ تمہارا چچا اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے والا ہے.لڑکا بڑا دلیر تھا اس کا چچا کسی مہم کے لئے باہر گیا ہوا تھا جب وہ واپس آیا تو اس کے دروازہ میں داخل ہوتے ہی لڑکا تیر کمان لے کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عین اس کے دل کی طرف تیر کھینچ کر کہنے لگا گھوڑے پر سے اتر آؤ اور بادشاہت میرے حوالے کر دو ورنہ میں ابھی تمہیں مار ڈالوں گا.فوجی افسروں میں بھی یہ بات پھیل چکی تھی انہوں نے جب ایک چھوٹے بچے کو اس دلیری کے ساتھ کھڑا ہوتے دیکھا تو اس کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ تمام نوجوان طبقہ اسی وقت باغی ہو گیا اور نجاشی کے ساتھ مل گیا.اس کے چچا نے جب یہ نظارہ دیکھا تو سمجھا کہ مقابلہ فضول ہے اور بادشاہت اس کے حوالے کر دی.یہی واقعہ نجاشی نے اپنے درباریوں کو یاد دلایا اور کہا تم زیادہ سےزیادہ یہی کہہ سکتے ہو کہ ہم یہ تخت تم سے چھین لیں گے مگر جس خدا نے میری اس وقت مدد کی تھی جب میں چھوٹا بچہ تھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب اتنی لمبی عمر اس کے فضل اور احسان کے ماتحت گذارنے کے بعد میں اس سے غداری کروں.یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا.خدا کی تعلیم
Page 363
یہی ہے کہ مسیحؑ نبی تھا اس سے بلند کوئی اور مقام میں مسیحؑ کو ہرگز نہیں دے سکتا.جب اس نے یہ بات کہی تو درباری ڈر کر خاموش ہو گئے اور بادشاہ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ آزادی کے ساتھ اس کے ملک میں رہیں.دیکھو یہ کتنی عجیب بات ہے ابرہہ کا لشکر خانۂ کعبہ کو گرانے جاتا ہے بلکہ خانۂ کعبہ کو نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے جاتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ یہی تھا کہ جو موعود آئے گا عیسائیوں میں سے آئے گا کسی اور قوم میں سے نہیں.اس نے چاہا کہ عرب جو ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور جن کے اتحاد کا نقطۂ مرکزی خانۂ کعبہ ہے ان کو عیسائیت کے مقابلہ میں مغلوب رکھنے کے لئے خانۂ کعبہ کو گرادے اور ان کے شیرازہ کو بکھیر دے تاکہ نبیٔ عربی کے خیال کے ماتحت وہ ایک مرکز پر جمع نہ ہو سکیں.مگر وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانے کے لئے کھڑا ہوا تھا اسی کے ہاں مسلمانوں نے پناہ لی.(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام ذکر الـھجرۃ الاولٰی الی ارض الحبشۃ) یہ مت خیال کرو کہ مسلمانوں کی اصل جگہ تو مکہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاص صحابہ تو مکہ ہی میں رہے تھے پھر نجاشی نے انہیں کس طرح پناہ دی اور کس طرح اس قوم کے پروں کے نیچے انہوں نے ترقی کی.حقیقت یہ ہے کہ اس ہجرت کی وجہ سے مکہ کے مسلمان بھی کفار کے ظلم و ستم سے بچ گئے تھے.چنانچہ جتنا قتل و غارت اور خون خرابہ ہجرت حبشہ سے پہلے ثابت ہے اتنا خون خرابہ ہجرتِ حبشہ کے بعد ثابت نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اگر مسلمانوں کو مارنا چاہتے تھے تو اس لئے تو نہیں کہ زید یا بکر سے انہیں کوئی دشمنی تھی وہ اس لئے مارنا چاہتے تھے کہ اسلام کا وجود ہی مٹ جائے.مگر اب مسلمانوں کا اسی۸۰ فی صدی حصہ حبشہ میں جا چکا تھا اور صرف بیس۲۰ فی صدی حصہ مکہ میں رہ گیا تھا.وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے بیس۲۰ فی صدی مسلمانوں کو مار بھی دیا تو کچھ نہیں بنے گا کیونکہ حبشہ میں اسلام کا درخت اپنی جڑیں پکڑ چکا ہے.پس مسلمانوں کے حبشہ جانے کی وجہ سے اس مار پیٹ کا سلسلہ بھی ختم ہوگیا جو مکہ میں جاری تھی.بعد میں بے شک انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں قید بھی رکھا اور انہوں نے آپ کو بھوکا اور پیاسا بھی رکھا.اسی طرح مسلمانوں کو انہوں نے اور کئی رنگوں میں دکھ دیئے مگر بہرحال ان کا پہلا رنگ بدل گیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کو مارنے پیٹنے کا اتنا فائدہ نہیں.پس ہجرت کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ترقی مل گئی اور ملی بھی اسی قوم کے زیر سایہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے.اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پالا گویا وہی جو آپ کی تباہی کی کوشش کر رہا تھا اسی کے گھر میں آپ پل رہے تھے.اسی قسم کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بعض اور بھی واقعات ہیں مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں
Page 364
ثقیف قوم میں پرورش پائی حالانکہ یہ ثقیف قوم وہی تھی جس نے ابرہہ کو راہنما دیئے تھے تاکہ وہ جائے اور خانہ کعبہ کو گرائے.گویا وہی قوم جو خانۂ کعبہ کو گرانے کے لئے اپنی خدمات پیش کرتی ہے اسی کے گھر میں خانۂ کعبہ کا مقصود پرورش پاتا اور اپنی زندگی کے کئی سال بسر کرتا ہے اس زمانہ میں بھی دیکھ لو مہدویت کے مدعیوں سے جہاں بھی مقابلہ کیا ہے انگریزوں نے کیا ہے(اردو انسائیکلو پیڈیا زیر لفظ مہدی) مگر پھر انگریزوں کے سایہ تلے ہی مسیح موعودؑ نے ترقی کی ہے.لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھاہے کہ میں انگریزوں کے سایہ تلے پلا ہوں.ان نادانوں سے کوئی پوچھے کیا خدا نے یہ نہیں کیا کہ موسٰی فرعون کےسایہ تلے پلے؟ کیا خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو نجاشی کے سایہ تلے نہیں پالا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو دشمنوں کے سایہ تلے ترقی دیتا ہے جو ان کی صداقت کا ایک ثبوت اور ان کی جماعتوں کے لئے ایک قابلِ فخر بات ہوتی ہے.جب مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ میں انگریزوں کے سایہ تلے پلا ہوں تو درحقیقت ان الفاظ کے ذریعہ آپ نے اپنے دشمن کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب نشان دیکھو کہ جو مہدی کا سب سے بڑا دشمن تھا اسی کے سایہ کے نیچے خدا نے مجھے ترقی دی.غرض اللہ تعالیٰ کی یہ ایک عظیم الشان سنت چلی آتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوئی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بھی ظاہر ہوئی کہ وہ اپنی جماعتوں کو اپنے دشمنوں کے سایہ تلے ترقی دیتا ہے.حضرت مسیحؑ ناصری کے زمانہ میں بھی یہی بات ہوئی.یہودی آپ کے متعلق بار بار کہتے تھے کہ یہ بادشاہ ہونے کا مدعی ہےاور اس کا مقصد یہ ہے کہ روما کی حکومت کو تباہ کر دے مگر اسی روما کی حکومت کے سایہ تلے آپ نے پرورش پائی اور پھر ایک دن وہ آپ کی غلامی میں بھی داخل ہو گئی گویا آپ نے اس حکومت کو تو تباہ کیا مگر اس طرح کہ اس کا مذہب بدل دیا اور اسے عیسائی بنا لیا.خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والوں کی تباہی کے متعلق وہیری کے بعض اعتراضات وہیری اس جگہ لکھتا ہے کہ اس واقعہ کا مضمون کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں(تفسیر القرآن از وہیری جلد ۴ صفحہ ۲۷۹).اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حملہ آور تھے وہ مسیحی تھے جن کو قرآن کریم اہل کتاب کہتا ہے اور جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ کافر تھے.پس وہ کہتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان اسے خدا کا کلام تو کہتے ہیں مگر ان میں اتنی عقل نہیں کہ وہ یہ بے جوڑ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اہل کتاب کو مشرکوں کے مقابلہ میں سزا دی گئی.وہ کہتا ہے مسلمان اس کو نشان قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ نشان نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہتک ہے کیونکہ سزا مشرکوں کو ملنی چاہیے تھی نہ کہ اہلِکتاب کو.
Page 365
دوسری بے جوڑ بات یہ ہے کہ خود تاریخ مانتی ہے کہ صنعاء کے گرجا کی ہتک کی گئی اور اس میں کسی عرب نے پاخانہ کر دیا.اسی طرح تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس گرجا کو آگ لگائی گئی اور یہ آگ لگانے والے بھی عرب تھے.پس قصور سراسر عربوں کا تھا.عربوں نے ایک معبد کی ہتک کی اور پھر خدا کی عبادت گاہ کو آگ لگانے کی کوشش کی.مگر قرآن کریم کا خدا نعوذ باللہ ایسا بے سمجھ ہے کہ جو گرجا کی ہتک کا بدلہ لینے کےلئے گیا تھا اس پر تو عذاب نازل کر دیا اور جنہوں نے ایک معبد کی ہتک کی تھی اور بلاوجہ قوم کو اشتعال دلایا تھا ان کی تائید کر دی.یہ عجیب خدا ہے کہ جو مظلوم تھا اس پر اس نے عذاب نازل کر دیا اور جو ظالم تھا اس کی تائید کر دی.جو خدا کو ماننے والے تھے ان کو تو مار دیا اور جو مشرک اور بت پرست تھے ان کو بچا لیا.پادری وہیری Wherry جس کے اعتراضات کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ایک امریکن پادری تھا جس کی بڑی عمر لدھیانہ میں گذری.اس نے قرآن کریم کی ایک تفسیر بھی لکھی ہے(تفسیر القرآن از وہیری مقدمہ صفحہ ۸) اور گو اس کا نام تفسیر ہے مگر حقیقتاً وہ تمام عیسائی معترض جنہوں نے کبھی اور کسی زمانہ اور کسی ملک اور کسی زبان میں اسلام پر اعتراض کئے تھے وہ تمام اعتراضات اس نے اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے.ایک ایسا انسان جس کو قرآنی علوم کی واقفیت ہو اور جو اس کے وسیع مطالب کا صحیح رنگ میں علم رکھتا ہو اس کے لئے یہ ایک دلچسپ تفسیر ہے.کیونکہ یہ اتنی بے جوڑ، اتنی لغو، اتنی دور از کار اور اتنی پیش پا افتادہ باتوں پر مشتمل ہے کہ انہیں پڑھ کر حیرت آتی ہے.اور تعجب آتا ہے کہ وہ انسان جس نے یہ تعلیم دی تھی کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تُو اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے(متی باب ۵ آیت ۳۹) اس کے پیروؤں کا آج اگر عمل ہے تو اس بات پر کہ جس نے تیری سات پشت کو بھی تھپڑ نہیں مارا تو اس کو بھی اور اس کی سات پشت کو بھی تھپڑ مار.اس سورۃ کے نیچے اسے اعتراض کرنے کے لئے اور تو کچھ نہیں ملا کیونکہ اس کے نزدیک یہ صرف ایک قصہ ہے گو ہمارے نزدیک صرف قصہ نہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی بات بطور قصہ بیان نہیں اگر وہ کسی گذشتہ قصہ کو بیان بھی کرتا ہے تو درحقیقت اس میں آئندہ کے متعلق پیشگوئی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ گویہ واقعہ پیچھے ہو چکا ہے مگر آئندہ زمانہ میں بھی ایک اسی قسم کا واقعہ ہونے والا ہے.بہرحال اس کو صرف ایک گذشتہ قصہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اسے اور تو کوئی اعتراض نہیں سوجھا صرف یہ اعتراض سوجھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن اس کو نشان قرار دیتا ہے حالانکہ یہ کیسا نشان ہوا کہ جن کو سزا ملی وہ اہلِ کتاب میں سے تھے جو قرآن کریم کے نزدیک بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک سچی کتاب پر ایمان رکھنے والے تھے اور جن کے مقابلہ میں یہ معجزہ دکھایا گیا وہ مکہ کے بت پرست اور مشرک
Page 366
تھے کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک طرف تو قرآن اپنے آپ کو خدائی کتاب کہتا ہے اور دوسری طرف وہ یہ بتاتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ میں کچھ بھی غیرت نہیں تھی اس نے مسیح ناصری پر ایمان لانے والوں اور اپنی ایک کتاب کو الہامی تسلیم کرنے والوں کو تو ذلیل کیا اور مارا اور جو بُت پرست تھے جن کو تمام قرآن میں برا بھلا کہا گیا ہے اور جو یقیناً اہل کتاب کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے ان کو بچایا اور ان کی تائید میں اپنے فرشتے نازل کئے.وہ کہتا ہے یہ ایک نہایت ہی لغو اور عقل کے خلاف بات ہے اور اس سے خدا تعالیٰ پر بہت بڑا الزام عائد ہوتا ہے.دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ خود تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک عرب گیا اور اس نے صنعاء کے گرجا میں پاخانہ کر دیا اور اس طرح مسیحی قوم کے ایک مقدس معبد میں پاخانہ کر کے اس نے تمام قوم کو مشتعل کیا.جب اس کی خطا ثابت ہے اور ابرہہ اسی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے گیا تھا تو چاہیے تھاکہ ابرہہ کی تائید کی جاتی مگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو شخص محض اپنے معبد کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے گیا تھا اسے تو شدید سزا ملی اور جس قوم کا ایک فرد گرجا میں پاخانہ کر کے آگیا تھا اس قوم کی تائید کی گئی حالانکہ سزا ظالم کو ملنی چاہیے تھی نہ کہ مظلوم کو.جہاں تک اس کی عبارت اور اعتراض سے پتہ چلتا ہے پادری وہیری کو نفس واقعہ پر کوئی اعتراض نہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ ابرہہ نے حملہ نہیں کیا تھا یا حملہ کرنے تو گیا تھا مگر مارا نہیں گیا تھا.وہ اس تمام واقعہ کو تسلیم کرتا ہے مگر اس میں سے جو درسِ عبرت نکالا گیا ہے پادری وہیری کو اس پر اعتراض ہے اور وہ اسے درست تسلیم نہیں کرتا.لیکن اگر واقعہ درست ہے تو درسِ عبرت پر اسی صورت میں اعتراض ہو سکتا ہے جب یہ کہا جائے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو پیش آگیا اسے نشان یا معجزہ قرار دینا درست نہیں.پس پادری وہیری اگر کہہ سکتا تھا تو یہ کہ تم جو کہتے ہو کہ خدا نے ابرہہ کو ہلاک کیا اور اس پر عذاب نازل کیا یہ درست نہیں واقعہ ٹھیک ہے اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں.ابرہہ واقعہ میں حملہ کے لئے گیا اور ایک بہت بڑا لشکر اپنےساتھ لے گیا مگر جو تباہی اس پر واقعہ ہوئی یا وہ تباہی جس کا سامنا اس کے لشکر کو کرنا پڑا وہ کوئی خدائی فعل نہیں تھا بلکہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو پیش آگیا اور اس کی وجہ سے مکہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو پیش کرنا اور ابرہہ کی تذلیل کرنا درست نہیں.اور واقعہ میں اگر یہ اتفاقی حادثہ ثابت ہو تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ اس سے خانۂ کعبہ کی کوئی عظمت ظاہر ہوتی ہے اورنہ ابرہہ کی تذلیل ہوتی ہے.جیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص حج کے لئے جائے مگر بمبئی میں پہنچتے ہی اسے ہیضہ ہو جائے اور وہ مر جائے.اب کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو اس پر اس لئے عذاب نازل ہو اہے کہ وہ حج کے لئے جارہا تھا.ہر شخص اسے اتفاقی حادثہ قرار دے گا یا ہو سکتا ہے کہ حاجیوں کا کوئی جہاز جا رہا ہو اور سمندر میں طوفان آجائے اور وہ جہاز غرق ہو جائے مگر کوئی شخص اسے عذاب
Page 367
قرار نہیں دے گا.اگر کوئی شخص ہم پر اعتراض کرے کہ وجہ کیا ہے کہ دو چار سو حاجی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اور تم اسے عذاب قرار نہیں دیتے؟ تو ہم کہیں گے صرف یہی ایک جہاز تو نہیں تھا جو آج حاجیوں کو لے کر گیا ہر سال کئی کئی جہاز حاجیوں کو لے کر جاتے ہیں اور ان میں سے اکثر سلامتی کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر آج کوئی جہاز غرق ہو اہے تو یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے جو اسے پیش آگیا عذاب نہیں.اگر عذاب ہوتا تو اکثروں پر نازل ہوتا.اسی طرح اگر حج کے لئے جاتے ہوئے کسی کو ہیضہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر عذاب نازل ہو ااور جب ہم سے کوئی پوچھے کہ تم اسے عذاب کیوں نہیں قرار دیتے؟ تو ہمارا جواب یہی ہو گا کہ ہرسال دو چار لاکھ حاجی حج کے لئے جاتا ہے اور قریباً سارے کا سارا سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچ جاتا ہے اگران میں سے ایک دو کو ہیضہ ہو گیا ہے تو یہ بہرحال ایک اتفاقی حادثہ ہے اگر اکثر مر جاتے تو بے شک شبہ ہو سکتا تھا کہ کہیں یہ خدائی عذاب نہ ہو مگر اکثروں کا بچ جانا اور صرف ایک دو کا مرنا ثبوت ہے اس بات کا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی.اسی طرح وہیری اس واقعہ کے متعلق بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا اور چونکہ اتفاقی طو رپر یہ مصیبت آگئی تھی اس لئے اسے عذاب قرار نہیں دیا جا سکتا.اور چونکہ اسے عذاب قرار نہیں دیا جا سکتا اس لئے اس واقعہ سے خانۂ کعبہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا استدلال کرنا بھی درست نہیں اور یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر یہ اتفاقی حادثہ ثابت ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابرہہ پر عذاب آیا اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے خانۂ کعبہ کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے ہمارے یہ دونوں دعوے غلط ثابت ہو جائیں گے.غرض پادری وہیری کا اعتراض اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے اگر ابرہہ کی تباہی کو اتفاقی حادثہ قرار دیا جا سکے.اس لئے سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ تھا؟ جو باتیں اس سورۃ کی تفسیر میں مَیں پہلے کہہ چکا ہوں وہ کافی سے بھی زیادہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہم اسے ہرگز اتفاقی حادثہ نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ خانۂ کعبہ کی حفاظت اور اس کے محفوظ رہنے کا وعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے چلا آتا ہے اور عرب لوگ اس بات کے مدعی تھے کہ خانۂ کعبہ پر کوئی شخص حملہ نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو خدا خود اس گھر کو اس کے حملہ سے بچائے گا.چنانچہ ابرہہ کا واقعہ اس کا ثبوت ہے اور حضرت عبدالمطلب نے اسے اسی امر کی طرف توجہ دلائی تھی جب ابرہہ نے انہیں کہا کہ تمہارے دو سو۲۰۰ اونٹ جو میری فوج پکڑ کر لے آئی ہے تم ان دو سو اونٹوں کو تو مانگتے ہو اور خانۂ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا معبد ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے تم کیسے جاہل اور عقل سے کورے انسان ہو.تو حضرت عبدالمطلب نے اسے یہی جواب دیا کہ میرا سوال ہی آپ کے اس اعتراض کو ردّ کر دیتا ہے.میرا سوال یہ
Page 368
ہے کہ میرے دو سو اونٹ مجھے واپس دے دیئے جائیں یہ مطالبہ میں نے کیوں کیا اس لئے کہ میں دو سو اونٹ کا مالک ہوں.پس میں نے اس سوال سے ہی تم کو یہ بتایا ہے کہ مالک کو اپنی چیز کی پروا ہوتی ہے اور وہ اس کا ضائع ہونا برداشت نہیں کر سکتا.میرا عقیدہ یہ ہے کہ خانۂ کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہی اس کا مالک ہے اگر اپنے اونٹوں کے لئے میں تمہارے در پر سوالی بن کر آگیا ہوں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ خدا کو اپنے اس گھر کی پروا نہیں ہو گی.اگر وہ اس گھر کا مالک ہے تو جس طرح مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے اسی طرح اسے بھی اس گھر کی فکر ہو گی اور وہ اسے تمہارے حملہ سے ضرور بچائے گا.اس جگہ حضر ت عبدالمطلب نے اپنی بات کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے یہی دلیل دی ہے کہ ہمارا عقیدہ خانۂ کعبہ کے متعلق یہ ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اس نے آپ اس گھر کو بچانے کا وعدہ کیا ہوا ہے.اگر ہمارا یہ عقیدہ درست ہے تو پھر اگر تم نے خانۂ کعبہ پر حملہ کیا تو وہ تمہیں ضرور تباہ کر دے گا.یہ واقعہ اپنی ذات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ خانۂ کعبہ کی حفاظت کا وعدہ دو ہزار سال سے چلا آرہا تھا اور عرب لوگ اس بات کے مدعی تھے کہ جو شخص اس گھر پر حملہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا(تاریخ الطبری ذکر بقیۃ خبر تبع ایام قباذ).اس دعویٰ کے بائیس سو سال بعد ایک شخص اٹھتا اور بیت اللہ پر حملہ کرتا ہے ایک بہت بڑا لشکر اس کے ساتھ ہے تمام قسم کے ساز و سامان سے وہ مسلّح ہے، اسے اپنی طاقت پر بہت بڑا ناز ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ خانۂ کعبہ کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں مگر باوجود ان تمام باتوں کے وہ اور اس کا لشکر ایسی بری طرح تباہ ہوتے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتی ہے کون شخص ہے جو اس واقعہ کو اتفاقی قرار دے سکے کیا دو ہزار سال سے عربوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ خانۂ کعبہ پر کوئی شخص حملہ نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو مارا جائے گا.اور دو ہزار سال میں صرف ایک شخص کا حملہ کرنا اور تباہ ہو جانا یہ اتفاق کہلا سکتا ہے.بے شک اگر عربوں کا خانۂ کعبہ کے متعلق کوئی دعویٰ نہ ہوتا اور ابرہہ اور اس کا لشکر تباہ ہو جاتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک اتفاقی امر ہے.وہ حملہ کے لئے آئے تھے مگر ان میں ایک بیماری پھوٹ پڑی اور وہ مر گئے.لیکن دو ہزار سال سے مکہ والوں کا ایک دعویٰ کرنا اور نسلاً بعد نسلٍ اس عقیدہ پر قائم رہنا اور پھر جب ابرہہ اپنا لشکر لے کر آیا تو ان کا ابرہہ کے سامنے بھی اس پیشگوئی کا اعلان کر دینا اور پھر اس پیشگوئی کے عین مطابق اس کا مارا جانا یہ سب کچھ اتفاق کس طرح ہو گیا؟ دنیا میں قاعدہ ہے کہ جب کبھی کوئی کیس سامنے آئے اس کے متعلق سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ بادی النظر میں سچا ہے یا جھوٹا.یا پہلا اثر انسانی طبیعت پر کیا پڑتا ہے اور اس کے متعلق کون سے نتائج ہم فوری طو رپر حاصل کر سکتے ہیں.اس نقطۂ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو مکہ والوں کی طرف سے دو ہزار سال سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر خانۂ کعبہ پر کوئی شخص حملہ کرے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا.اور جب دو ہزار سال کے بعد ایک دشمن اٹھا اور اپنا لشکر لے کر
Page 369
خانۂ کعبہ کو گرانے کے لئے بڑھا تو مکہ کے سردار نے اسے کہہ دیا کہ ہمارے ہاں یہ روایت چلی آتی ہے کہ اگر کسی نے اس گھر پر حملہ کیا تو وہ تباہ ہو جائے گا.اس لئے تم اس ارادہ کو ترک کر دو مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا اور آخر وہی کچھ ہوا جو مکہ کے سردار نے اسے کہاتھا اور جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے پیشگوئی چلی آتی تھی یعنی وہ مارا گیا اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا.اس تمام واقعہ کو دیکھتے ہوئے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بادی النظر میں یہ کیس مکہ والوں کے حق میں جاتا ہے.پس اب ہمارا فرض نہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا.بلکہ عیسائیوں کا فرض ہے کہ اگر وہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دیتے ہیں تو ثابت کریں کہ یہ کس طرح اتفاقی حادثہ ہے.دو ہزار سال سے خانۂ کعبہ کی حفاظت کے متعلق ایک پیشگوئی تھی وہ پیشگوئی ابرہہ کو یاد کرا دی گئی مگر اس نے اپنے ارادہ کو ترک کرنے سے انکار کیا اور فیصلہ کیا کہ میں ضرور اس گھر کو گراؤں گا.جب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تو ابھی اس نے خانۂ کعبہ کو گرانے کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ خدا کا عذاب اس پر نازل ہو گیا اور وہ نہایت ذلیل اور مقہور ہو کر مرا.اس دو ہزار سالہ پیشگوئی کو سننے اورپھر اس پیشگوئی کو سب کے سامنے پورا ہوتے دیکھنے کے بعد ہم پر یہ کس طرح فرض ہو گیا کہ ہم یہ ثابت کریں کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا.یہ عیسائیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے اتفاقی حادثہ ثابت کریں اور اپنی دلیل ہمارے سامنے پیش کریں.اگر ان کی دلیل ہمارے سامنے آئے گی تب ہمارا فرض ہو گا کہ ہم اس کو توڑیں لیکن جب تک ان کی دلیل ہمارے سامنے نہیں آتی بار ثبوت بہرحال عیسائیوں کے ذمہ ہے.دوسرا جواب یہ ہے کہ جو چیز ایک تسلسل میں واقعہ ہو وہ چیز خود اپنی ذات میں اپنی صداقت کا ثبوت ہوتی ہے اگر ایک زنجیرہو تو یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ زنجیر کا حق مقدّم ہوتا ہے کڑی کا حق مقدّم نہیں ہوتا کیونکہ کڑی بہرحال زنجیر کے تابع ہوتی ہے.ایک شخص کے متعلق اگر ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ دس سال سے برابر سچ بولتا چلا آرہا ہے کوئی شخص کہتاہے کہ اسے نو سال سے برابر سچ بولتے دیکھ رہا ہوں، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسے آٹھ سال سے برابر سچ بولتے دیکھ رہا ہوں کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسے سات سال سے برابر سچ بولتے دیکھ رہا ہوں تو یہ تسلسل خود اپنی ذات میں اس کے راستباز ہونے کا ثبوت ہو گا.اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے اور اس کے متعلق کہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو بادی النظر میں وہ بات سچی سمجھی جائے گی جو دس سال سے ثابت ہے.وہ بات سچی نہیں سمجھی جائے گی جو نئی پیش کی جارہی ہے اور دس سال کے تجربہ کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے ہم دوسرے شخص کو اس الزام سے بری قرار دیں گے ہاں الزام لگانے والے سے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر تمہیں اپنے الزام پر اصرار ہے تو تم اس کا ثبوت لاؤ.وہ اگر کہے کہ ثبوت اسے پیش کرنا چاہیے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا تو ہر شخص الزام لگانے والے کو احمق قرار دے گا.
Page 370
ہم کہیں گے ثبوت تیرے پاس ہونا چاہیے.اس کے سچا ہونے کی تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زندگی کا ایک لمبا تسلسل بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے.یہی وہ دلیل ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعویٰ نبوت کے وقت قوم کے سامنے پیش کی.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت دعویٰ نبوت فرمایا تو کسی نے کہا پاگل ہو گیا ہے کسی نے کہا جھوٹ بولتا ہے، کسی نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے، کسی نے کہا بتوں کی ناراضگی کی اسے سزا ملی ہے، غرض عجیب عجیب قسم کی باتیں آپ کے متعلق مشہور ہونے لگیں.جب ان باتوں کا چرچا ہوا تو ایک دن آپ نے تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور ان کےسامنے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں فرمایا کہ تم میرے رشتہ دار ہو، مجھے دیر سے جانتے ہو، میری عادات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو تم یہ بتاؤ کہ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ان سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ہرگز نہیں آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ کی راستبازی مسلّم ہے اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت شعاری کا اثر ان سے منوانے کے لئے ایک اور بات کہی.بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جنگل ہوتا ہے اور ان میں اگر کوئی لشکر چھپنا چاہے تو بڑی آسانی سے چھپ سکتا ہے.لیکن بعض ایسے چٹیل میدان ہوتے ہیں کہ ان میں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی.دور دور تک آدمی دکھائی دیتا ہے.مکہ کے اردگرد بھی ایسی جگہ ہے.اس میں کوئی بڑا لشکر چھپ نہیں سکتا.جب مکہ والوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو راست باز پایا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا جرّار لشکر تم پر حملہ کرنے کے لئے چھپا بیٹھا ہے تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ یہ ایک ایسی بات تھی جو قطعی طور پر ناممکن تھی اگر کوئی لشکر مکہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے تو وہ اس پہاڑی کے پیچھے چھپ ہی نہیں سکتا مگر باوجود اس کے کہ یہ بات بالبداہت ناممکن تھی انہوں نے کہا ہاں اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا بیٹھا ہے تو باوجود اس کے کہ ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی ہوں گی ہم آپ کی بات کو درست تسلیم کرلیں گے.یہ آپ کی صداقت کی کتنی زبردست دلیل ہے جس کا مکہ والوںنے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اگر ایک ناممکن اور نظر نہ آنے والی بات بھی آپ بیان کریں گے تو ہم اسے ضرور مان لیں گے.ہم اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دیں گے مگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے جب انہوںنے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی صداقت اور آپ کی راست بازی کا علی الاعلان اقرار کیا تورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری صداقت پر تمہیں ایسا ہی یقین ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حکم دیاہے کہ میں تمہیں ڈراؤں اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکوں اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ
Page 371
گے.اس پر وہی لوگ جو ابھی چند منٹ پہلے آپ کو راستباز کہہ رہے تھے ہنسی اور مذاق کرتے ہوئے منتشر ہو گئے.اور کسی نے کہا جھوٹ بولتا ہے، کسی نے کہہ دیا پاگل ہو گیا ہے، کسی نے کہہ دیا دماغ خراب ہو گیا ہے.لیکن یہی واقعہ تم کسی معقول انسان کے سامنے رکھو تو وہ کیا کہے گا؟ وہ انہی لوگوں کو پاگل قرار دے گا جو ابھی آپ کو راست باز قرار دے رہے تھے اور ابھی آپ کو جھوٹا قرار دینے لگے.غرض واقعات کے تسلسل کی زنجیر بالبداہت تسلیم شدہ ہوتی ہے اور اگر کوئی اس کے خلاف بات کہتا ہے تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دلیل لائے دوسرے کا فرض نہیں ہوتا کہ اس کی بات کو توڑے.دو ہزار سال سے عربوں کا یہ دعویٰ تھا کہ خانۂ کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہ اس کی آپ حفاظت کرے گا.عربوں کے اس دعویٰ کے متعلق تم کہہ لو کہ یہ ایک وہم تھا، شک تھا، وسوسہ تھا، بے دینی تھی، کفر تھا لیکن بہرحال جو کچھ بھی تھا عرب کہتے تھے کہ خانۂ کعبہ محفوظ رہے گا اور دو ہزار سال سے زنجیر کی یہ کڑی مسلسل چلی آتی تھی اور لوگ اسی ڈر کے مارے خانۂ کعبہ پر حملہ نہیں کرتے تھے.جب دو ہزار سال گذر جاتے ہیں تو ایک شخص اٹھتا اور خانۂ کعبہ پر حملہ کرتا ہے اور وہ حملہ کرنے والا زندہ نہیں رہتا بلکہ بری طرح تباہ ہوجاتا ہے.ایسی صورت میں جبکہ اس واقعہ کا تسلسل دو ہزار سال سے ثابت ہے یقیناً ہر شخص عربوں کے دعویٰ کی ہی تصدیق کرے گا.اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ واقعہ جو ایک لمبی زنجیر کی ایک کڑی نظر آرہا ہے اصل میں اس زنجیر کی کڑی نہیں کسی اور زنجیر کی کڑی ہے یا ایک بے تعلق کڑی ہے.تو بارثبوت اس کے ذمہ ہے لیکن جہاں تک اس زنجیر کے تسلسل کا سوال ہے اس کے لحاظ سے ماننا پڑتا ہے کہ مکہ والوں نے اس بارہ میںجو دعویٰ کیا تھا وہ بالکل صحیح اور درست تھا اور واقعات نے بھی ان کے دعویٰ کی تصدیق کر دی.اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا تو اس کا فرض ہے کہ وہ دلیل لائے مسلمان کا فرض نہیں کہ وہ اس کے اتفاقی حادثہ نہ ہونے کےد لائل دے.بہرحال پیشگوئی کے لحاظ سے بھی اور واقعاتی زنجیر کے لحاظ سے بھی مکہ والوں کا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے.اگر کوئی شخص اس کے خلاف کہتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ دلیل لائے مگر وہ دلیل نہ وہیری نے پیش کی ہے اور نہ کسی اور عیسائی پادری نے پیش کی ہے.دوسری بات اس بارہ میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ اتفاقی واقعہ تو نہیں تھا.تھا تو یہ ایک نشان ہی مگر خدا کو یہ نشان مسیحیوںکے خلاف نہیں دکھانا چاہیے تھا بلکہ مسیحیوں کی تائید میں دکھانا چاہیے تھا.چونکہ یہ نشان مسیحیوں کے خلاف دکھایا گیا ہے اس لئے ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے.یہ بھی بالکل پاگل پن کی بات ہو گی اگر خدا نے یہ نشان دکھایا ہے تو یقیناً ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہیری کی عقل سے بہرحال خدا تعالیٰ کی عقل مقدّم ہے اگر وہ اسے خدا تعالیٰ کا نشان سمجھنے کے باوجود یہ کہتا ہے کہ خدا نے مسیحیوں کے خلاف یہ نشان کیوں دکھایا اسے تو مسیحیوں کی تائید میں
Page 372
نشان دکھانا چاہیے تھا تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہتے ہیں کہ کوئی پٹھان حدیث پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ ذکر آگیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے نواسہ حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیا جب آپ رکوع کے لئے گئے تو آپ نے بچے کو اتار کر ایک طرف بٹھا دیا.دوسری طرف اس نے فقہ میں یہ مسئلہ پڑا ہوا تھا کہ حرکت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جب اس نے حدیث میں یہ واقعہ پڑھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو نماز پڑھتے اپنی گود میں اٹھا لیا اور رکوع کے وقت اسے اتار دیا تو کہنے لگا ’’خو محمد صاحب کا نماز ٹوٹ گیا‘‘.کسی سننےو الے نے اسے جواب دیا کہ بے وقوف نماز تو سکھائی ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے ان پر کس طرح اعتراض ہو سکتا ہے.اسی طرح یہ فیصلہ کرنا کہ نشان مسیحیوں کی تائید میں دکھایا جائے یا مسیحیوں کے خلاف دکھایا جائے خدا تعالیٰ کا کام ہے.اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نشان خدا تعالیٰ نے دکھایا ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ نے نعوذباللہ بڑی بے وقوفی کی کہ مسیحیوں کی تائید میں اس نے نشان نہ دکھایا ویسی ہی بات ہے جیسے پٹھان نے کہہ دیا تھا کہ ’’خو محمد صاحب کا نماز ٹوٹ گیا.‘‘اگر تمہاری عقل میں ایک بات نہیں آتی تب بھی جبکہ ثابت ہو کہ یہ واقعہ اتفاقی نہ تھا تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم جو کچھ سمجھتے ہو یہ تمہاری عقل کی غلطی ہے خدا تعالیٰ کی عقل بہرحال تمہاری عقل پر مقدم ہے.گو دنیا میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو خدا کی عقل سے زیادہ سمجھتے ہیں.ابھی تھوڑے دن ہوئے ایک گریجوایٹ جو وکیل بھی تھا مجھ سے ملنے کے لئے آیا اور اس نےمجھ سے بعض سوالات کئے.جب میں نے اس کے تمام سوالات کا جواب دے کر بتایا کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ہے یا نہیں اگرخدا تعالیٰ ہے تو پھر اعتراض نہیں ہو سکتا.کیونکہ پھر سوال یہ ہو گا کہ آپ کی عقل مقدم ہے یا خدا تعالیٰ کی تو اس پر وہ صاحب بے اختیار ہو کر بولے کہ میری عقل مقدم ہے.یہ بات سن کر ان کے ساتھی بھی ہنس پڑے کہ یہ کیسی خلاف عقل بات ہے.مگر حقیقت یہی ہے کہ تمام اعتراضات کے دور ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اپنی بات کو سچا ثابت کر سکتے تھے تو اسی طرح کہ یہ کہتے کہ خدا تعالیٰ سے میں زیادہ عقل مند ہوں.اگر اس نے ایک بات کی ہے اور میری عقل اسے نہیں مانتی تو میں اسے کیوں قبول کروں.یہی پادری وہیری کی حالت ہے کہ وہ اسے اتفاقی حادثہ بھی نہیں کہہ سکتے.وہ اس واقعہ سے انکار بھی نہیں کر سکتے.لیکن اعتراض یہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مسیحیوں کو کیوں مارا اور ان کے مقابل پر مشرکین مکہ کو کیوں نہ مارا.لیکن بہرحال ایسے شخص کو بھی جواب دینا پڑتا ہے اس لئے میں اس کے اعتراضات کا جواب دیتا ہوں.پہلا جواب یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ مسیحی تو اہل کتاب تھے اور مکہ کے لوگ بت پرست.پھر مسیحیوں پر کیوں عذاب آیا اور بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بچا لیا خود بڑی بے دینی اور جہالت کی بات ہے.بھلا خدا کو مسیحی یا
Page 373
غیرمسیحی سے کیا تعلق ہے؟ خدا تو عدل و انصاف اور راستی اور صداقت کو دیکھتا ہے اگر تو وہ یہ کہتا کہ ابرہہ حق پر تھا اور مکہ والے ناحق پر.اس لئے عذاب مکہ والوں پر آنا چاہیے تھا نہ کہ ابرہہ پر.تب بھی کوئی بات تھی(اس نے آگے چل کر یہ دلیل بھی دی ہے مگر اس کا جواب میں الگ دوں گا) لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ مسیحیوں کو کافروں کے مقابلہ میں کیوں سزا دی گئی.یہ تو ویسی ہی ظالمانہ بات ہے جیسے بعض لوگ اپنے آدمی کی رعایت کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ظالم ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ وہ مظلوم ہوتا ہے.کیا ہمارا خدا بھی نعوذ باللہ ایسا ہے کہ وہ عدل و انصاف کو تو مدّ ِنظر نہ رکھے اور محض مسیحی ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تائید کرتا پھرے.اگر پادری وہیری اپنے خدا کو ایسا سمجھتے ہیں تو الگ بات ہے اسلام جس خدا کو پیش کرتا ہے وہ اس قسم کا ظالمانہ سلوک نہیں کرتا بلکہ اسلام تو بنی نوع انسان کو بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ تم مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکو خواہ وہ تمہارا باپ ہو یا بھائی.دوست ہو یا کوئی اور عزیز رشتہ دار.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہؓ بیٹھے تھے کہ آپ نے فرمایا اُنْصُـرْ اَخَاکَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا.اے میرے پیروؤ! میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہوں یا مظلوم.صحابہؓ کو یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تعلیم کے خلاف نظر آئی اور وہ حیران ہوئے کہ یہ الٹی بات کیا کہی جارہی ہے کہ مظلوم کے علاوہ ظالم کی بھی مدد کرو.چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد کرنے والی بات تو ہماری سمجھ میں آتی ہے مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کرنے کا یہ مطلب ہے کہ تم اسے ظلم سے روکو کیونکہ اگر وہ ظلم کرے گا تو تباہ ہوجائے گا.(بخاری کتاب المظالم باب أعن اخاک ظالمًا اَوْ مَظْلُوْمًا) اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بھی روک دیا.مگر ایسی طرز پر کہ بات ان کے دلوں میں گھر کر گئی.اگر آپؐیہ فرماتے کہ ظالم کی مدد نہ کرو تو کئی لوگ یہ کہنے لگ جاتے کہ اپنے بھائی بندوں کی تو بعض دفعہ مدد کرنی ہی پڑتی ہے مگر جب آپ نے اسی بات کو اس رنگ میں بیان فرمایا کہ اگر تم ظالم کی مدد کرو گے تو تم خود اسے تباہ کر دو گے تو مقصد بھی پورا ہو گیا اور بات بھی سننے والوں کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی.پس اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ حق و انصاف کی مدد کی جائے لیکن یہ پادری صاحب خدا تعالیٰ کو نعوذ باللہ انسان سے بھی زیادہ بداخلاق سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی خاص مذہب اور خاص فرقہ کی تائید کیا کرے، عدل اور انصاف کو ملحوظ نہ رکھا کرے.ہم تو نہیں سمجھتے کہ عیسائی مذہب سچا ہے.لیکن فرض کرو کہ وہ سچا ہے تو کیا پادری وہیری یہ سمجھتا ہے کہ اگر سچے مذہب کا پیرو ظلم بھی کرے تب بھی اس کی تائید کی جائے اور مظلوم کو اس کا حق نہ دیا جائے.بے شک مغربی قوموں کا آج کل یہی طریق عمل ہے مگر کوئی شریف
Page 374
اور انصاف پسند آدمی اس طریق کو درست ماننے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا.واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ اہلِ مکہ کا معبد گرانے کے لئے نکلا تھا اور یہ ایک نہایت ہی ظالمانہ فعل تھا بے شک وہ مسیحی تھا لیکن وہ ظالم مسیحی تھا اور ظالم کی مدد کرنا تو کسی شریف انسان کا کام بھی نہیں ہو سکتا کجا یہ کہ خدا تعالیٰ سے یہ امید رکھی جائے کہ وہ ظالم کی مدد کرے اور مظلوم کو کچل دے محض اس لئے کہ ظالم مسیحی ہےاور مظلوم بت پرست.دوسری بات یہ ہے کہ یہ حملہ کفار پر نہیں تھا کفار کو تو اس نے امان دینے کا وعدہ کیا تھا.یہ حملہ سراسر خانۂ کعبہ پر تھا.چنانچہ دیکھ لو قلیس میں پاخانہ کس نے پھرا تھا ایک عرب نے پھرا تھا مگر وہ حملہ کے لئے خانۂ کعبہ کی طرف آدوڑا.کیا خانۂ کعبہ نے پاخانہ پھرا تھا یا خانۂ کعبہ پاخانہ پھرا کرتا ہے؟ پاخانہ پھرنے والا ایک عرب تھا مگر وہ حملہ خانۂ کعبہ پر کرتا ہے بے شک عیسائی تعلیم کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی سج جاتی ہے کیونکہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قصور لوگوں نے کیا اور صلیب پر اللہ تعالیٰ نے مسیحؑ کو چڑھا دیا.لیکن کوئی عقل منداور شریف انسان اس قسم کی بات کو جائز قرار نہیں دے سکتا کہ قصور کوئی کرے او رسزا کسی کو دی جائے.بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو سزا دینی جائز نہیں.چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب بن یامین کو اپنے ساتھ لے کر مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ کسی طرح وہ بن یامین کو اپنے پاس رکھ لیں.مگر انہوں نے اپنے اس ارادہ کا کسی پر اظہار نہ کیا.اس کے بعد اللہ تعالیٰ نےا یسے سامان پیدا کر دیئے کہ جن کے ماتحت وہ قانوناً اپنے بھائی کو پکڑ سکتے تھے.سرکاری پیالہ کہیں گم ہو گیا اور اس کی ادھر ادھر تلاش شروع ہو گئی.ابھی اس پیالہ کی تلاش ہی ہو رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شک کی بنا پر اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ اگر چوری کی کوئی چیز کسی کے پاس سے نکل آئے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا چور کی یہی سزا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے.تھوڑی دیر گذری تو بن یامین کے سامان میں سے سرکاری پیالہ نکل آیا.اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب بن یامین کو واپس جانے نہیں دیا جائے گا.یہ سن کر ان کا ایک بھائی آگے بڑھا اور اس نے کہا اس لڑکے کاباپ بہت بڈھا ہے اور اس کا پہلے ہی ایک بیٹا گم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اسے بڑی تکلیف ہے اگر یہ بھی اب واپس گھر نہ پہنچا تو اس کی تکلیف اور بھی بڑھ جائے گی.اس لئے اے بادشاہ میں اپنے آپ کو اس کی جگہ پیش کرتا ہوں مجھے قید کر لیا جائے اور اس کو رہا کر دیا جائے.اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ظالم نہیں کہ بے قصور کو پکڑ لوں اورجس کا قصور ہو اسے جانے دوں.گویا بائبل بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ظلم کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے یہ نہایت ظالمانہ فعل ہے مگر عیسائی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ گناہ لوگوں نے کیا اور صلیب خدا نے حضرت مسیح کو دے دی.دوسرے مذاہب
Page 375
بے شک اس عقیدہ کو نہیں مانتے مگر اس میں کسی مذہب کا سوال نہیں عقل اور شرافت بھی نہیں مانتی کہ مجرم کوئی ہو اور سزا کسی کو دی جائے.اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے غور کرو کہ صنعاء کے گرجا میں کوئی جاہل اور بدتہذیب عرب پاخانہ کر دیتا ہے اس پر بادشاہ کو غصہ آتا ہے مگر اس غصہ میں وہ اس عرب کو نہیں مارتا جس نے پاخانہ کیا تھا، وہ اس عرب کے رشتہ داروںکو بھی نہیں مارتا، وہ اس عرب کی قوم کو بھی نہیں مارتا، وہ اپنے لشکر کے ساتھ کئی سو میل کا سفر طے کرتے ہوئے اس لئے جاتا ہے کہ خانۂ کعبہ کو جو تمام عرب کا مقدّس مقام تھا گرادے.کون عقل مند کہہ سکتاہے کہ یہ انصاف تھا.کون عقلمند کہہ سکتا ہے کہ یہ اقدام ہتک کا بدلہ لینے کے لئے کیا گیا تھا.میں تاریخی روایات سے ثابت کر چکا ہوں کہ مکہ کے لوگوں کو ابرہہ نے یہ پیغام بھیجا کہ میں تم کو مارنے کے لئے نہیں آیا میں صرف خانۂ کعبہ کو گرانے کے لئے آیا ہوں.اگر تم لوگ میرے راستہ میں روک نہ بنے تو میں خانۂ کعبہ کو گرا کر واپس چلا جاؤں گا اگر انسان نے قصور کیا تھا تو انسان ہی اس قصور کا ذمہ وار تھا اور اگر سزا دی جا سکتی تھی تو اسی عرب کو جس نے گرجا میں پاخانہ کیا.اگر زیادہ طیش آیا تھا تو اس کے بھائی بندوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا.اگر اس سے بھی بڑھ کر غصہ آتا تو اس کی قوم پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا.مگر یہ کیا کہ قصور تو ایک جاہل عرب کرتا ہے اور حملہ خانۂ کعبہ پر کیا جاتا ہے.یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی عیسائی ایک ہندو سے لڑے تو غصہ میں حکومت ہندوؤں کا کوئی مندر گرا دے یا کوئی ہندو کسی عیسائی سے لڑے تو غصہ میں ہندو حکومت مسیحیوں کا کوئی گرجا گرا دے.آخر دونوں باتوں میں کوئی جوڑ تو ہونا چاہیے.یہ جوڑ تو نظر آسکتا ہے کہ زید نے قصور کیا تو زید کے بھائی بندوں کو بھی پکڑ لیا گیا مگر یہ کہ زید قصور کرے اور ایک قومی معبد کو گرانے کے لئے حملہ شروع کر دیا جائے ان دونوں کاآپس میں کوئی جوڑ نہیں.پس ابرہہ کا فعل بتاتا ہے کہ وہ ان کفار سے لڑنے کے لئے نہیں گیا تھا جن کے ایک فرد نے اس کے گرجا کی ہتک کی تھی بلکہ وہ اس لئے گیا تھا کہ خانۂ کعبہ کو گرا دے.پس وہ خدا کے حضور ایک خطرناک مجرم تھا اور اس کے فعل کے جواز میں یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے گرجا کی ہتک کا بدلہ لینے گیا تھا.تیسرے جیسا کہ میں ثابت کر چکا ہوں ابرہہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ عربوں کے اتحاد کو توڑ دے کوئی مذہبی غرض اس حملہ کے پیچھے نہیں تھی ورنہ دنیا میں اور ہزاروں گرجے موجود تھے کبھی کسی گرجا کے بننے کے بعد عیسائیوں کی طرف سے یہ کوشش ہوئی کہ غیراقوام کے افراد بھی اس کو اپنا مقدس مقام قرار دے لیں؟ لیکن ابرہہ نے ادھر گرجا بنایا ادھر اس نے یہ کوشش شروع کر دی کہ خانۂ کعبہ کی بجائے لوگ اس کی زیارت کے لئے آیا کریں اور اس نےبعض عرب رؤوسا کو رشوتیں دے دے کر اس پراپیگنڈہ کے لئے مقرر کیا.آخر اس کا مذہب سے کیا تعلق تھا.
Page 376
ہرشخص کےد ل میں اپنے مذہب کا احترام ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اپنے مذہب کے خلاف دوسرے سے کوئی بات سنے اور عرب بھی اس عقیدت کے جذبات سے خالی نہیں تھے ابرہہ اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا تھا کہ عربوں کو خانۂ کعبہ سے گہری عقیدت ہے اور وہ اس کو چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہو سکتے مگر اس کے باوجود اس کا بعض عرب رؤوسا کو خانۂ کعبہ کے خلاف پراپیگنڈہ کرنے کے لے مقرر کرنا اور پھر خانۂ کعبہ کو گرانے کی کوشش کرنا بتاتا ہے کہ یہ ایک سیاسی چال تھی جو غلبۂ عیسائیت کے لئے اختیار کی گئی تھی اور جس کے پیچھے اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ عربوں میں ایک نبی کی آمد کے متعلق جو احساس پیدا ہو رہا ہے اس کے خلاف ان کی توجہ کو پھیر دے اور عربوں کا شیرازہ بالکل بکھیر دے.یہ ایک نہایت ہی گندی سیاسی غرض تھی جس کے لئے اس نے حملہ کیا پس ایسا شخص ضرور سزا کا مستحق تھا اور خدا تعالیٰ نے اسے سزا دی.دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ وہ ہتک کا بدلہ لینے گیا تھا اس کو سزا کیوں ملی.اس کا ایک جواب تو آچکا ہے کہ ہتک تو ایک عرب نے کی تھی مگر وہ خود عرب والوں سے امان کا وعدہ کرتا ہے.چنانچہ جہاں بھی عربوں نے اس سے یہ کہا ہے کہ خانۂ کعبہ کو بے شک گرا لو ہم تمہارے ارادہ میں مزاحم نہیں ہوتے وہاں اس نے ان سے صلح کر لی ہے اگر وہ ہتک کابدلہ لینے گیا تھا تو اسے اس عرب پر غصہ آنا چاہیے تھا جس نے گرجا میں پاخانہ کیا.اس کے قبیلہ پر غصہ آنا چاہیے تھا.اس کی قوم پر غصہ آنا چاہیے تھا مگر یہ کیا کہ وہ سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کرتا ہے اور عربوں سے بار بار کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی عداوت نہیں اگر تم میرے راستہ میں روک نہ بنو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا.پس یہ کہنا کہ وہ ہتک کابدلہ لینے کے لئے گیا تھا واقعات کے بالکل خلاف ہے.دوسرے انسان کی ہتک کا کسی معبد سے بدلہ لینا عقل کے بالکل خلاف ہے اور پھر مرکزی معبد کو گرانے کی کوشش کرنا تو اور بھی قابلِ نفرین فعل ہے.یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ صنعاء کا گرجا عیسائی قوم کا کوئی مرکزی معبد نہیں تھا لیکن خانۂ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے ایک مرکزی معبد چلا آتا تھا.اگر ایک عام معبد کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے کسی مرکزی معبد کو گرانے کی کوشش کرنا عیسائیوں کے نزدیک جائز ہے تو کیا وہ پسند کریں گے کہ مسلمان اپنی بعض مساجد کی ہتک کا بدلہ لینے کے لئے یروشلم کا گرجا گرا دیں؟ لاہور میں ریلوے سٹیشن کے قریب ایک پرانی مسجد تھی جس میں ریلوے کا ٹوٹا پھوٹا سامان رکھا جاتا تھا.انگریزوں نے اپنے زمانہ میں اس میں بعض دفعہ کتے بھی باندھے ہیں.مسلمانوں نے اس مسجد کو آزاد کرانے کے لئے ایک دفعہ ایجی ٹیشن کی جس پر ریلوے کا کباڑ خانہ اس میں سے اٹھا لیا گیا اور مسجد بحال کر دی گئی مگر اس کے بعدبھی یہ مسجد ویران پڑی رہی اب شاید
Page 377
پاکستان بن جانے کی وجہ سے اس مسجد کی آبادی کا بھی کوئی سامان ہو گیا ہو ورنہ اس سے پہلے تو یہ ہمیشہ ویران پڑی رہتی تھی.اب کیا مسلمانوں کا حق ہے کہ اس بناء پر کہ عیسائیوں نے ان کی ایک مسجد کی ہتک کی تھی یروشلم کا گرجا جا کر گرادیں.اگر وہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہوں تو ہم ان کے جواب کی معقولیت کو تسلیم کر لیں گے.لیکن اگر یروشلم کا گرجا گرانا تو الگ رہا اس کے گرانے کا ذکر سن کر بھی ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے تو یہ کون سا انصاف ہے کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ صنعاء کے گرجا میں ایک پاگل عرب نے پاخانہ کر دیا تھا اس لئے ابرہہ کے لئے یہ جائز ہو گیا تھا کہ وہ عربوں کے مقدّس ترین مقام خانۂ کعبہ پر جا کر حملہ کر دے.یقیناً اس نے جو کچھ کیا وہ ایک ظالمانہ فعل تھا اور ظالم کو ضرور سزا ملنی چاہیے تھی چنانچہ خدا تعالیٰ نے اسے سزا دی.سورۃ الفیل میں آخری زمانہ کے متعلق پیشگوئی میں جیسا کہ اوپر بتا چکا ہوں اس سورۃ میں درحقیقت آخری زمانہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے عیسائی دنیا نے آپ کے دین کو روکنے اور اس کی ترقی کے امکانات کو مسدود کرنے کی کوشش کی تھی.چنانچہ جب وہ علامات انہیں نظر آئیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ نبیٔ عربی دنیا میں پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے خانۂ کعبہ کا رخ کیا تاکہ عرب جس نقطۂ مرکزی پر جمع ہو سکتے ہوں اسے توڑ دیا جائے اور وہ موعود جس کا عرب میں شدت کے ساتھ انتظار کیا جارہا تھا اس کے راستہ میں روکیں پیدا ہو جائیں.لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے احترام اور آپ کے اعزاز میں خانۂ کعبہ کو گرنے نہیں دیا.اللہ تعالیٰ اس نشان کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ پھر ایک زمانہ میں عیسائی دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور آپ کی قوت کو مٹانے کی کوشش کرے گی اور تسلّی دیتا ہے کہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے.جس خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے بھی پہلے آپ کا ادب اور احترام کیا تھا اس خدا کے متعلق کون یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ وہ آپؐکی پیدائش کے بعد، آپؐکے دعوٰیٔ نبوت کے بعد، آپ کی بے مثال اور حیرت انگیز قربانیوں کے بعد، آپؐکی خدا تعالیٰ سے بےانتہا محبت کے اظہار کے بعد، آپ کی اعلیٰ درجے کی نیک اور پاک جماعت دنیا میں قائم ہو جانے کےبعد، آپ کی کامل اور ہرقسم کے نقائص سے منزہ شریعت لوگوں کے سامنے پیش ہو جانے کے بعد، آپؐکے دین اور مذہب کے تمام دنیا میں پھیل جانے کے بعد، اب اس ہتک کو برداشت کر لے گا کہ اسے تباہ ہونے دے اور دشمن کو اس کے بدارادوں میں کامیاب کر دے.کوئی عقلمند جو ذرا بھی ان واقعات پر نگاہ رکھنےو الا ہو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے ایک لحظہ کے لئے بھی یہ بات نہیں مان سکتا کہ اس مقابلہ
Page 378
میں عیسائیت کو کامیابی حاصل ہوسکتی ہے یقیناً ایک مسلمان کے لئے اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ وہ ٹکر جو اسلام اور عیسائیت میں ہونے والی ہے اس کا وہی کچھ نتیجہ نکلے گا جو ابرہہ کے وقت میں نکلا جبکہ وہ خانۂ کعبہ سے ٹکر لینے کے لئے آیا.لیکن افسوس کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے.اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ والی سورۃ موجود ہے اور وہ اسے ہر روز دیکھتے اور پڑھتے ہیں انہیں اس بات پر یقین نہیں کہ اس لڑائی میں آخر اسلام فتحیاب ہو گا اور عیسائیت ہارے گی.یقین سے میری مراد صرف منہ کی لاف و گزاف نہیں بلکہ وہ معقول یقین مراد ہے جس کے ساتھ انسان کا عمل شامل ہوتا ہے.بے شک جہاں تک زبان کے دعووں کا سوال ہے ہر مسلمان کہتا ہے کہ اسلام جیتے گا.لیکن جہاں تک اسلام کی فتح اور کامیابی پر یقین کا سوال ہے ننانوے فیصدی مسلمان یہ یقین نہیں رکھتے کہ اس لڑائی میں اسلام جیتے گا.شاید آپ لوگ یہ خیال کرتے ہوں کہ میں نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو واقعات کے خلاف ہے.فلسطین میں مسلمان لڑ رہے ہیں ہندوستان میں بہت کچھ کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں پھر یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان ننانوے فیصدی اسلام کی فتح پر یقین نہیں رکھتے.میرا جواب یہ ہے کہ یقین کے ساتھ ہمیشہ عمل شامل ہوتا ہے وہ ایمان ہرگز ایمان نہیں کہلا سکتا جس کے ساتھ عمل کی قوت نہ ہو.وہ ایک وسوسہ تو کہلا سکتا ہے.اسے کمزوریٔ اخلاق تو کہا جا سکتا ہے.مگر وہ سچا ایمان ہرگز نہیں ہو سکتا.اگر سچا ایمان ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان عمل نہ کرے.اگر کسی کو پتہ ہوکہ میرا بچہ علاج سے بچ جائے گا تو کیا دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بچہ کے علاج میں کوتاہی کرے؟ اگر وہ اس کے علاج میں کوتاہی کرتا ہے تو دو ۲باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے.یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے بالکل جاہل ہے اور جاہل میں ہرگز ایمان نہیں ہوتا.اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کےعارف اور عالم بندے ہی اس پر ایمان لایا کرتے ہیں.ا گر ایک شخص کے بچے کو نمونیا ہو جاتا ہے اور وہ اس کا علاج تو نہیں کرتا مگر یہ کہتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا تو کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتا ہے.یقیناً وہ ایک جاہل آدمی ہے جو ایک ڈھکوسلا خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اس کے ایمان کا ثبوت ہے.اور یا پھر وہ اپنے بچہ کے علاج کی طرف اگر توجہ نہیں کرتا تو اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے تو مر ہی جانا ہے ڈاکٹر کی فیسوں پر مجھے روپیہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے.لیکن جس شخص کو یقین ہو کہ میرا بچہ علاج سے ضرور اچھا ہو سکتا ہے اور جو خدا تعالیٰ کے قانون سے بھی جاہل نہ ہو وہ کبھی اپنے بچہ کے علاج میں غفلت سے کام نہیں لے سکتا.اگر مسلمانوں کو بھی یقین ہوتا کہ عیسائیت پر اسلام نے غالب آنا ہے تو وہ کوشش اور وہ قربانی کیوں نہ کرتے جو اس کے لئے ضروری تھی.
Page 379
انہیں یہ تو نظر ہی آتا ہے کہ بہ نسبت مسلمانوں کے عیسائی پردۂ زمین کے بہت زیادہ حصہ پر حاکم ہیں.وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ایک روپیہ کے بدلہ میں ان کے پاس ایک ایک لاکھ روپیہ ہے.وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک ایک تلوار کے مقابلہ میں ان کے پاس ایک ایک توپ ہے بلکہ ایک ایک توپ کا بھی سوال نہیں دس دس اور بیس بیس توپیں ہیں.وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لنگڑے ٹٹوؤں کے مقابلہ میں ان کے پاس ہوائی جہاز موجود ہیں.ان کو معلوم ہے کہ جتنے غلیلے ان کے گھروں میں ہیں ان سے زیادہ مسیحیوں کے پاس توپ کے گولے ہیں اور یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ اس پر قسم اٹھائی جاسکتی ہے.مگر اتنی بڑی مصیبت کے مقابلہ میں انہوں نے کیا تیاری کی ہے اور کون سی قربانیاں ہیں جو ان کی طرف سے پیش کی جارہی ہیں؟ میں نے ابھی چند دن ہوئے عراق کا ایک اخبار دیکھا جس میں فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بڑے زور کے ساتھ لکھا تھا کہ تم کہتے ہو ہمارے دلوں میں فلسطین کی بڑی محبت ہے تمہاری محبت کی علامت تو یہی ہے کہ ستّر ستّر پونڈ پر تمہاری رائفلیں تمہارا دشمن لے گیا اور تم نے کچھ بھی خیال نہ کیا کہ ہم یہ کیا کررہے ہیں.گویا دس پونڈ کے بدلہ میں جب تمہیں ستّر پونڈ مل گئے تو تم اپنے ملک سے غداری کرنے کے لئے تیار ہوگئے.جب تمہاری اپنے ملک سے محبت کی یہ حالت ہے تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ فلسطین میں تمہیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے یہی نمونہ مسلمانوں نے اس جگہ دکھایا.جن دنوں مسلمانوں کی بہو بیٹیاں سکھ اٹھا اٹھا کر لے جارہے تھے ان دنوں بعض غدار مسلمان مسلم لیگ سے رائفلیں خرید کر سکھوں کے آگے بیچ دیا کرتے تھے.یہ مسلمانوں کی عملی حالت ہے اور پھر وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محض نعروں سے وہ جیت جائیں گے.ان کے اللہ اکبر کے نعرے بھی جھوٹے ہیں، ان کے دعوے بھی جھوٹے ہیں اور ان کا یہ خیال کہ ہمیں اسلام پر یقین ہے یہ بھی محض دھوکا اور فریب ہے.نہ انہیں خدا سے محبت ہے نہ رسولؐ سے محبت ہے نہ قرآن سے محبت ہے نہ اسلام سے محبت ہے.جب تک وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کریں گے ان کی ترقی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو گی.اب بھی فلسطین میں شور پڑا ہوا ہے اور خیال کیاجاتا ہے کہ وہاں مسلمانوں کو بڑی بھاری طاقت حاصل ہے.حالانکہ ہمارے آدمی وہاں موجود ہیں اور ان کی چٹھیاں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں جو اتنی بھیانک اور خوفناک ہوتی ہیں کہ انہیں پڑھ کر دل لرز جاتا ہے.ہمارے ایک مبلّغ نے لکھا ہے کہ اس جگہ کا وزیر جنگ اس سے ملا اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں پاکستان کو لکھو کہ وہ کسی طرح ہماری مدد کرے ہمارے دعوے ایک دھوکے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے.اس وقت حالت یہ ہے کہ مصر، شام، عراق، لبنان اور شرق اردن وغیرہ سب نے مل کر حملہ کیا ہوا ہے مگر یہود برابر جیت رہے ہیں.اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ تو
Page 380
اعلانوں پر اعلان ہو رہے ہیں کہ ہم یہود کو مار ڈالیں گے مگر تیاری کچھ نہیں تھی.نتیجہ یہ ہوا کہ جب لڑائی کا وقت آیا تو دشمن نے جیتنا شروع کر دیا.اب کہا جاتا ہے کہ مسلمان کیا کریں.برطانیہ اور امریکہ نے تو سامان بھیجنا بند کر دیا ہے.مگر سوال یہ ہے کہ آج سے سال بھر پہلے تو انہوں نے سامان بھیجنا بند نہیں کیا ہوا تھا.پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے آج سے سال بھر پہلے تیاری نہ کی؟ اور آج یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ نے ہمیں سامان بھجوانا بند کر دیا ہے.حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو یہ یقین ہوتا کہ خدا ان کی اسی رنگ میں مدد کرے گا جس طرح اس نے ابرہہ کے مقابلہ میں خانۂ کعبہ کی کی تو یقیناً وہ عمل بھی کرتے.وہ قربانی اور ایثار سے بھی کام لیتے اور اسلام کی ترقی کے لئے اپنی ہر چیز قربان کر دیتے.اگر وہ ایسا کرتے تو خدا تعالیٰ کی نصرت ان کی طرف دوڑتی ہوئی آجاتی.مگر قربانی کا مادہ یوں ہی تو پیدا نہیں ہو جاتا.قربانی ہمیشہ یقین کے ساتھ پیدا ہوتی ہے.جس شخص کو یقین ہو کہ دشمن اسے شکست نہیں دے سکتا وہ قربانی کرنے پر دلیر ہوتا ہے اور جس شخص کو یقین ہو کہ اگر وہ مر بھی گیا تو وہ جنت میں جائے گا وہ بھی اپنی کسی چیز کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کرتا.بہرحال یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو جرأت پیدا کرتی ہے.یقین ہی ایک ایسی چیز ہے جو قربانی اور ایثار کا مادہ پیدا کرتی ہے اور یقین ہی ایسی چیز ہے جو بڑی بڑی مشکلات میں انسان کے قدم کو متزلزل ہونے سے بچاتی ہے.اور ایک مسلمان کے یقین کو اس سے زیادہ مضبوط کرنے والی اور کیا شے ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ.اے مسلمان! تجھے پتہ ہے یا نہیں کہ اصحابِ فیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا.اگر تجھے اس واقعہ کا علم ہے تو تُو عیسائیت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر کیوں مایوس ہوتا جا رہا ہے تیرا خدا آج بھی وہی خدا ہے جو اصحاب فیل کے وقت تھا.وہ خدا مفلوج نہیں ہو گیا، وہ خدا مسلول نہیں ہو گیا، وہ خدا بڈھا نہیں ہو گیا، وہ خدا ناکارہ نہیں ہو گیا، اس خدا کی طاقتیں ماری نہیں گئیں، وہ خدا اب بھی ویسا ہی زندہ ہے جیسے پہلے زندہ تھا اور اب بھی ویسی ہی طاقتیں رکھتا ہے جیسی پہلے طاقتیں رکھتا تھا.جب تمہارا زندہ اور طاقتور خدا موجود ہے تو تم یہ خیال بھی کس طرح کر سکتے ہو کہ وہ اس مصیبت میں تمہاری مدد نہیں کرے گا اور اسلام کی کشتی کو منجدھار میں چھوڑ دے گا.اگر یہ یقین اور ایمان کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو مال اور جان کی قربانی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی.وہ اپنی جان کی قربانی بھی بےحقیقت سمجھتا ہے.اپنے بیوی بچوں کی جان کی قربانی بھی بے حقیقت سمجھتا ہے اور اپنی جائیداد کی قربانی بھی بےحقیقت سمجھتا ہے.آج مسلمان اگر پھر اپنے اندر ایسا یقین پیدا کر لیں تو آج بھی وہ دنیا کی ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ قربانی اور ایثار کا یہ نظارہ دکھائیں تو ان کے ایمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے ان کی مدد کے لئے اتر آئے اورکہے کہ میرے
Page 381
بندوں نے قربانی پیش کر دی ہے اب اگر میں ان کی مدد کے لئے نہ گیا تو مجھ پر بے وفائی کا الزام عائد ہو گا.مگر افسوس اس طرف کوئی توجہ نہیں.چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ ہے.کہیں منسٹریوں کے جھگڑے کی طرف توجہ ہے کہیں کسی اور بات کی طرف توجہ ہے.لیکن اگر توجہ نہیں تو اسی مقصود کی طرف جس سے ان کی زندگی اور ایمان وابستہ ہے.دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اس وقت خطرہ میں ہے.یہود اس کے دروازہ پر طاقت پکڑتے جار ہے ہیں اور یہود کے ارادے یہ ہیں کہ وہ سارے عرب کے علاقہ پر قبضہ کر لیں.کہا جاتا ہے کہ آج سے کئی سو سال پہلے جبکہ یہود کو کوئی طاقت حاصل نہیں تھی وہ مدینہ میں مسلمان بن کر گئے اور انہوں نے سرنگ لگا کر یہ کوشش کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک کو نکال لیں اور اس کی بے حرمتی کریں.اچانک اس وقت کے مسلمان بادشاہ کو خواب آگئی اور اللہ تعالیٰ نے رؤیا میں اسے وہ یہود دکھا دیئے جو یہ شرارت کر رہے تھے اور وہ گرفتار کر لئے گئے.اگر وہی قوم جس نے اپنی ذلّت اور بے کسی کے زمانہ میں بھی ہمارے آقا کی ہتک کرنے میں کوتاہی نہیں کی اسے عرب اور شام کی حکومت مل گئی تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گی.پس کتنا بڑا خطرہ ہے جو اس وقت اسلام کو درپیش ہے.مگر افسوس کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو اصل مقصود ہے وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے حالانکہ اس وقت قربانی اور صرف قربانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے اسلام دنیا میں پھر زندہ ہو سکتا ہے.اگر ہم اس لڑائی میں مارے بھی جاتے ہیں تو کیا ہوا عزت کی ایک گھنٹہ کی زندگی ہزار سالہ بے عزتی کی زندگی سے بہتر ہوتی ہے.یقیناً کوئی باغیرت مومن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ بے عزتی کی زندگی بسر کرے وہ عزت کی موت کو بے عزتی کی زندگی سے ہزار درجہ بہتر سمجھے گا.غرض اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ کے ذریعہ آئندہ زمانہ کے متعلق ایک بہت بڑی پیشگوئی فرمائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں پھر مسیحیت اپنے زور میں آکر اسلام کو توڑنے کی کوشش کرے گی مگر جس طرح سابق میں ہوا اللہ تعالیٰ آئندہ زمانہ میں بھی اسلام کو دشمن کے حملہ سے بچائے گا.اور اس کا وہی انجام کرے گا جو اصحاب الفیل کا ہوا.جیسا کہ میں اوپر اشارہ کر چکا ہوں زمانۂ بعثت اولیٰ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے شروع کر دیئے تھے.کہتے ہیں ’’ہونہار برو اکے چکنے چکنے پات.‘‘ جب انہوں نے سنا کہ آنے والے نبی کا نام محمد ہو گا تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دیں شاید یہی اصل محمد ہوجائے.اس بڑھتی ہوئی رَو کو دیکھ کر عیسائیت کو سخت فکر پیدا ہوا اور اس نے چاہا کہ خانۂ کعبہ کو تباہ کر دے تاکہ عرب
Page 382
کی ترقی کے امکانات بالکل مٹ جائیں.اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا عام رجحان مسیحیت موعودہ اور مہدویت کی طرف تھا کیونکہ زمانۂ مسیحیت بالکل قریب آچکا تھا.پہلی بارہ۱۲ صدیوں کو دیکھو اور پھر پچھلی ایک صدی کو دیکھو تو تمہیں معلوم ہو گاکہ گذشتہ بارہ۱۲ صدیوں میں جتنے مہدویت کے مدعی گذرے ہیں اس سے دس گنا زیادہ مدعی صرف پچھلی ایک صدی میں ہوئے ہیں.یہ دس گنا فرق ثبوت ہے اس بات کا کہ مسیحیت اور مہدویت کے زمانہ کے قرب کی وجہ سے لوگوں میں ایک رَو پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی چنانچہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عیسائیت کو اپنے متعلق فکر پیدا ہو گئی تھی اسی طرح اس زمانہ میں بھی اس رَ وکو دیکھ کر عیسائیت کو فکر پڑ گئی اور اس نے سمجھا کہ اس طرح عیسائیت اسلام کے مقابلہ میں کمزور ہو جائے گی.لیکن جس طرح اس زمانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے حبشہ کی عیسائی حکومت میں پناہ لی جس کا ایک گورنر خانۂ کعبہ کو گرانے کے لئے آیا تھا.اسی طرح اس دوسرے زمانہ میں بھی مہدیٔ موعودؑ نے انہی کے سایہ تلے پناہ پائی جن کو مہدویت کے کچلنے کی فکر تھی.قادیان کے متعلق ایک اعتراض اور اس کا جواب اس جگہ جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والی یہ بات ہے کہ بعض مخالفین یہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ قادیان کو جماعت احمدیہ اپنا مقدّس مقام قرار دیا کرتی تھی مگر وہ اس وقت ہندوؤں اور سکھوں کے قبضہ میں ہے.ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت قادیان سے احمدیوں کا نکالا جانا بھی درحقیقت اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اور گو بظاہر یہ فعل ہندوستانیوں کا نظر آتا ہے لیکن اصل میں یہ ساری کارروائی لارڈ مونٹ بیٹن مسیحی کی ہے.چنانچہ سب سے پہلے اس کے متعلق میں نے مضامین لکھے تھے کہ گورداسپور کا علاقہ انڈین یونین میں صرف کشمیر کی خاطر شامل کیا گیا ہے اور لارڈ مونٹ بیٹن کا اس میں یقینی ہاتھ ہے.لیکن اب گورنمنٹ پاکستان کے بعض افسروں اور ہندوستان سے باہر رہنے والوں نے بھی کئی مضامین میںیہ لکھا ہے کہ گورداسپور کا علاقہ جو ہندوستان کو دیا گیا وہ درحقیقت اسی لئے دیا گیا تھا تاکہ کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملایا جا سکے.لیکن اس سورۃ سے ہمارے دلوں کی ڈھارس بندھتی ہے اور یقین ہوتا ہے کہ جس طرح اصحابِ فیل پہلی دفعہ تباہ ہوئے اب بھی تباہ ہوں گے.حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا الہام ہے کہ شخصے پائے من بوسید ومن گفتم کہ سنگِ اسود منم (تذکرہ صفحہ۳۶) ایک شخص نے میرے پاؤں کو چوما اور میں نے کہا ہاں ہاں سنگِ اسود میں ہی ہوں.درحقیقت ہر زمانہ کا مامور اس کی جماعت کے لئے سنگِ اسود کا رنگ رکھتا ہے کیونکہ لوگ اسے چومتے اور اس کے اردگرد اکٹھے رہتے ہیں اور اس طرح
Page 383
دین کو تقویت حاصل ہوتی ہے.پس اس زمانہ میں دین کی تقویت صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے وابستہ ہے اور اس زمانہ میں روحانی سنگِ اسود آپ ہی ہیں گو جسمانی سنگِ اسود وہی ہے جو خانۂ کعبہ میں موجود ہے اسی طرح یہ سورۃ الفیل بھی آپ پر الہاماً نازل ہوئی ہے پھر جس طرح اصحاب الفیل کے پہلے حملہ میں اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنا تھا اسی طرح اب جو احمدیت پر حملہ ہو اہے وہ اسی لئے ہوا ہے کہ ہندو بھی جانتا ہے اور سکھ بھی جانتا ہے اور مسیحی بھی جانتا ہے کہ اگر اسلام نے غلبہ پایا تو احمدیت کے ذریعہ ہی غلبہ پائے گا.پس اب بھی اس کا اصل مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ کرنا ہے کیونکہ مسیح موعود کا کام اپنا وجود منوانا نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منوانا ہے.آپ خود فرماتے ہیں.ع وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے لیکن جس طرح گذشتہ زمانہ میں خانۂ کعبہ کو گرانے میں ابرہہ اور اس کا لشکر ناکام رہا تھا اسی طرح ہم جانتے ہیں اور اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور قوتیں مل کر بھی اگر اس سلسلہ کو جسے خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے مٹانا چاہیں تو وہ ساری طاقتیں مل کر بھی اس سلسلہ کو مٹا نہیں سکتیں.ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں.لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کی فوجیں ہماری تائید میں اتریں گی اور اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ کا نظارہ دنیا متواتر دیکھتی چلی جائے گی.یہاں تک کہ وہی شخص جس کو مسلمانوں نے اپنی نادانی سے ٹھکرا دیا ہے اسی کے ہاتھوں سے اسلام دنیا میں دوبارہ قائم ہو گا اور معترضین ہمارے سامنے نہایت شرمندگی کے ساتھ وہی کچھ کہتے آئیں گے جو یوسفؑ کے بھائیوں نے اس سے کہا اور ہماری طرف سے بھی انہیں یہی کہا جائے گا کہ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ١ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ١ٞ وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (یوسف:۹۳) یہ کتنی عجیب بات ہے کہ غیر دنیا، کافر دنیا، بے دین دنیا جس کا مقابلہ ہماری جماعت کر رہی ہے وہ تو جانتی ہے کہ احمدیت کی اشاعت میں ہی عیسائیت کی موت ہے لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ احمدیت کی اشاعت میں نعوذباللہ اسلام کی تباہی ہے.قادیان کے متعلق ایک عیسائی پادری کی رائے مجھے یاد ہے میری خلافت کے ابتدائی زمانہ میں پادری والٹر WALTER سکرٹری لٹریچر آل انڈیا وائی ایم سی اے پادری ہیوم HUME اور فورمن کرسچن کالج لاہور کے پرنسپل مسٹر لیوکس LUCAS مجھ سے ملنے کے لئے قادیان آئے اور مختلف امور پر گفتگو کرتے رہے.واپس جاکر مسٹر لیوکس نے کولمبو میں عیسائیوں کے سامنے ایک لیکچر دیا جس میں کہا کہ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ عیسائیت کی
Page 384
جنگ بڑے بڑے شہروں یا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لڑی جائے گی.لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اس وقت ایک ایسے گاؤں میں سے ہوکر آیا ہوں جس میں ریل بھی نہیں جاتی (اس وقت تک قادیان میں ریل نہیں آئی تھی) جس میں تار بھی نہیں(اس وقت تک قادیان میں تار بھی نہیںتھی) اور جو نہایت ہی ادنیٰ حیثیت میں ہے.زیادہ سے زیادہ اسے ایک معمولی قصبہ کہا جا سکتا ہے.مگر میں وہاں عیسائیت کے مقابلہ کی ایسی تیاری دیکھ کر آیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اسلام اور عیسائیت کی آئندہ جنگ جس میں یہ فیصلہ ہو گا کہ اب اسلام زندہ رہے یا عیسائیت.وہ کہیں اور نہیں لڑی جائے گی بلکہ قادیان کے قصبہ میں لڑی جائے گی.یہ فورمن کرسچن کالج کے پرنسپل کی رائے ایک سیلون کے اخبار میں چھپی تھی.مگر بدقسمتی سے وہی مسلمان جن کو ذلّت کے مقام سے نکالنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی سلسلہ کو قائم کیا تھا وہی اس عظیم الشان تحریک سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کے راستہ میں قسم قسم کی روکیں پیدا کرتے رہتے ہیں.اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی آنکھیں کھولے اور انہیں سچا ایمان اور تقویٰ نصیب کرے.اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍۙ۰۰۳ کیا (ان کو حملہ سے قبل ہلاک کر کے) ان کے منصوبہ کو باطل نہیں کر دیا.حلّ لُغات.ضَلَّـلَ.ضَلَّلَ کے معنے ہوتے ہیں سَیَّـرَہٗ اِلَی الضَّلَالِ (اقرب) اس کو ضلال کی طرف لے گیا یعنی دین یا حق یا رستہ سے اس کو دور کر دیا.یہاں مراد یہ ہے کہ کامیابی کے مقررہ راستہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا.کیونکہ کَیْد کے مقابلہ میں یہی معنے اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں پس اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ کے یہ معنے ہوں گے کہ کیا اس کی تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستہ سے دور نہیں کر دیا.تفسیر.حل لغات میں جو معانی بتائے گئے ہیں ان سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو تفسیر میں اوپر کر چکا ہوں وہی درست اور صحیح ہے.میں نے بتایا تھا کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر عیسائیوں کے منصوبوں کو ایک لمبے عرصہ تک باطل کر دیا.اسی لئے خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اَلَمْ يُضِلُّ كَيْدَهُمْ کیا خدا نے ان کی کید کو ہٹا نہیں دیا.بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ.تضلیل مصدر ہے اور مصدر عربی زبان میں ہمیشہ مستقل اور لمبے زمانہ کے لئے استعمال ہوتا ہے.مثلاً ہم کہتے ہیں قَامَ زَیْدٌ تو اس کے معنے ہوں گے زید کھڑا ہوا لیکن اگر ہم کہیں گے زَیْدٌ قَائِمٌ تو اس کے معنے یہ ہوں
Page 385
گے کہ زید دیر سے کھڑا ہے اور آئندہ بھی اس کے کھڑا رہنے کی امید ہے.اسی طرح اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس نے عیسائیوں کا منصوبہ صرف اس وقت باطل نہیں کیا جب وہ خانۂ کعبہ پر حملہ کرنے کے لئے آئے تھے.بلکہ اس نے بعد میں بھی ایک لمبے عرصہ تک ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور ان کی قوت کو کچل دیا تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھنے اور پنپنے کا موقع ملے اور آپؐکی ترقی کے راستہ میں کوئی روک واقع نہ ہو.چنانچہ اسلام کے مقابلہ میں عیسائی ایک لمبے عرصہ تک مغلوب رہے.مگر پھر قرآن کریم کی ہی پیشگوئیوں کے مطابق دوبارہ عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوا.اور اب الٰہی فیصلہ یہ ہے کہ وہ مسیحیت کو دوسری شکست انشاء اللہ ہمارے ہاتھ سے دے گا.وَّ اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَۙ۰۰۴ اور (پھر) ان (کی لاشوں) پر جُھنڈ کے جُھنڈ پرندے بھیجے.تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ۪ۙ۰۰۵ (جو) ان (کےگوشت) کو سخت قسم کے پتھروں پر مارتے (اور نوچتے) تھے.فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍؒ۰۰۶ اس طرح اس نے انہیں غلہ کے بیرونی چھلکے کی طرح کر دیا جس کے اندر کا دانہ کھایا گیا ہو.حلّ لُغات.اَبَابِيْلَ جمع ہے جس کا مفرد کوئی نہیں لیکن بعض کے نزدیک اس کا مفرد اِبّول ہے.(جامع البیان زیر آیت ھذا) اَبَابِيْلَ کے متعلق عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ ابابیل وہی پرندہ مراد ہے جسے اردو زبان میں بھی ابابیل کہتے ہیں مگر یہ درست نہیں.جس پرندے کو ہم ابابیل کہتے ہیں عربی زبان میں اسے ابابیل نہیں بلکہ خفّاش کہتے ہیں(لسان العرب).پس اس جگہ ابابیل سے کوئی خاص پرندہ مراد نہیں بلکہ اس کے معنے فِرَقٌ یعنی جماعتوں کے ہیں اور طَيْرًا اَبَابِيْلَ سے مراد یہ ہے کہ ’’جماعت در جماعت‘‘ اور ’’گروہ در گروہ‘‘ پرندے آئے.یہ لفظ انسانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیوانوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہےاور پرندوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے(القاموس الـمحیط).اگر گروہ در گروہ گھوڑے کسی جگہ کھڑے ہوں تو ان کے متعلق بھی ابابیل کا
Page 386
لفظ استعمال کر لیا جائے گا چنانچہ عربی زبان کا یہ محاورہ ہے کہ جَاءَتِ الْـخَیْلُ اَبَابِیْلَ جس کے معنے جَـمَاعَاتٌ مِّنْ ھٰھُنَا وَ ھٰھُنَا کے ہیں یعنی جماعت در جماعت اور گروہ در گروہ گھوڑے آئے کچھ یہاں سے اور کچھ وہاں سے.اسی طرح اگر انسانوں کا کوئی بہت بڑا لشکر جمع ہو تو اسے بھی ابابیل کہہ دیں گے اور مراد یہ ہو گی کہ بٹالین کے بعد بٹالین اور فوج کے بعد فوج آتی چلی گئی.پھر اس کے ایک معنے ’’جماعاتِ عظام‘‘ کے بھی ہوتے ہیں یعنی بڑی بڑی جماعتیں.اور ابابیل کے معنے اَقَاطِیْعُ تَتَّبِعُ بَعْضُھَا بَعْضًاکے بھی ہوتے ہیں (فتـح البیان زیر آیت ھذا) یعنی بڑے بڑے ٹکڑے جو ایک دوسرے کے بعد متواتر آتے چلے جائیں.پس اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ کے یہ معنے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف پرندے بھیجے جماعت در جماعت.کچھ یہاں سے کچھ وہاں سے وہ بڑے بڑے ٹکڑوں میں باری باری آتے تھے اور گروہ در گروہ تھے(اقرب).اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ چیچک سے اس لشکر میں سخت موت پڑی اور لاشیں میدان میں چھوڑ کر باقی لوگ بھاگ گئے اور چاروں طرف سے گدھ اور چیل آکر وہاں جمع ہوگئے تا ان کی لاشوں سے نوچ نوچ کر گوشت کھائیں.سِـجِّیْلٌ.سِـجِّیْلٌ چکنی مٹی کے ڈلے کی طرح کے پتھر کو کہتے ہیں(جامع البیان زیر آیت ھذا) لیکن لغت کے بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ کلمہ معرّب ہے اور سنگ ِگل سے بنا ہے جو فارسی زبان کا لفظ ہے یعنی پتھر اور مٹی.عرب چونکہ گ نہیں بول سکتے اس لئے جب فارسی سے عربی زبان میں یہ لفظ گیا تو سنگ کی بجائے سنج اور گِل کی بجائے جِل بن گیا(تفسیر ابن کثیر زیر آیت ھذا).پس سِـجِّیْلٌ کے معنے ہیں ایسا پتھر جو کئی پتھر کے ٹکڑوں اور مٹی کی تہوں سےبنا ہوا ہو یا پکی ہوئی مٹی کا پتھر جسے پنجابی زبان میں کھنگر کہتے ہیں.تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ کے معنے عام محاورہ کے مطابق تو یہ ہیں کہ ان پر سجیل مارتے تھے لیکن اس کے یہ معنے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو سجیل پر مارتے تھے.اور چونکہ مردار خور پرندوں کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ مردہ کا گوشت لے کر پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں اور گوشت کو بار بار پتھر پر مارتے جاتے اور کھاتے جاتے ہیں نہ معلوم اسے نرم کرتے ہیں یا اس کی صفائی کرتے ہیں.بہرحال چیلوں اور گدھوں کا یہ عام قاعدہ ہے کہ وہ گوشت کو کھاتے ہوئے پتھر پر مارتے جاتے ہیں.اس لئے یہی درست ہے کہ باء کے معنے اس جگہ’’پر‘‘ کے لئے جائیں خصوصاً جبکہ یہ ثابت ہے کہ یہ لوگ چیچک سے مرے تھے اور ان کی لاشیں تمام میدان میں پھیل گئی تھیں.پس آیت کا یہ مطلب ہے کہ مردار خور پرندے وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اور پتھروں پر مار مار کر کھانی شروع کر دیں.باء کے معنے جو اس جگہ عَلٰی کے کئے گئے ہیں یہ لغت سے بھی ثابت ہیں اور استعمالِ قرآن سے بھی ثابت
Page 387
ہیں.ایک عرب شاعر کہتا ہے أَرَبٌّ یَبُوْلُ الثُّعْلُبَانُ بِرَاْسِہٖ لَقَدْ ہَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَیْہِ الثَّعَالِبُ یعنی کیا وہ رب ہو سکتا ہے جس کے سر پر گیدڑ پیشاب کر جائیں.وہ چیز تو بہت ہی ذلیل ہے جس کے سر پر گیدڑ پیشاب کر جائے اور وہ اپنے آپ کو اس سے بچا بھی نہ سکے.یہ دراصل ایک صحابی کا شعر ہے جو انہوں نے اپنے زمانۂ بت پرستی میں کہا تھا.وہ ایک دفعہ بت کو اپنے ساتھ لے کر کسی سفر پر جارہے تھے کہ راستہ میں انہیں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی.پانی کچھ فاصلہ سے مل سکتا تھا.انہوں نے اسباب کو ایک جگہ رکھا اور چاہا کہ وہ جا کر پانی لے آئیں مگر پھر خیال آیا کہ میرے اسباب کی کون حفاظت کرے گا اگر پیچھے سے کوئی شخص آیا اور اسباب اٹھا کر لے گیا تو میں کیا کروں گا.اس پر انہوں نے بُت کو نکال کر اسباب کے پاس رکھ دیا اور اس سے کہا حضور میں تو پانی لینے چلا ہوں میرے آنے تک اسباب کی حفاظت فرمائیں.انہوں نے سمجھا کہ بت سے زیادہ اچھا محافظ اور کون ہو سکتاہے.مگر جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گیدڑ ٹانگ اٹھا کر اس بت کے سر پرپیشاب کر رہا ہے.یہ دیکھ کر ان کے دل میں ایسی سخت نفرت پیدا ہوئی کہ انہوں نے بُت کو وہیں پھینکا اور یہ شعر کہا کہ اَرَبٌّ یَبُوْلُ الثُّعْلُبَانُ بِرَاْسِہٖ لَقَدْ ہَانَ مَنْ بَالَتْ عَلَیْہِ الثَّعَالِبُ کیا وہ بت بھی رب ہو سکتاہے جو اپنے سر کو پیشاب سے نہیں بچا سکتا.گیدڑ آتا ہے اور ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے مگر اس میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ اپنے سر کو ہی پیشاب سے بچا سکے.اس شعر میں بِرَاْسِہٖ کے الفاظ ہیں مگر مراد یہ ہے کہ سر پر.اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ (اٰل عمران:۷۶) اگر تو اسے ایک ڈھیر پر امین بنائے.اس جگہ بھی باء کے معنے ساتھ کے نہیں بلکہ پر کے ہیں.ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ (التطفیف:۳۱) اس کے بھی لفظی معنے تو یہ ہیں کہ جب وہ ان کے ساتھ گذرتے ہیں.مگر مراد یہ ہے کہ جب وہ ان پر سے گذرتے ہیں تو آنکھیں مارتے ہیں.پس تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ کے معنے یہ ہوئے کہ وہ ان کو ایسے پتھروں پر مارتے تھے جو جلے ہوئے تھے.
Page 388
تفسیر.اَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ سے مراد ابرہہ کے لشکر پر ان کے مرنے کے بعد گدھوں وغیرہ کا اترنا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس تباہی کا نقشہ کھینچا ہے جو اصحاب الفیل پر آئی.آپ لوگوں نے دیکھا ہو گا کہ چیلیں اور گدھ اور کوے اور دوسرے مردار خور جانور جب کوئی بوٹی کھاتے ہیں تو کس طرح کھاتے ہیں.وہ مردار کی بوٹی توڑ کر ایک طرف جا بیٹھتے ہیں اور پتھر پر بیٹھ کر کبھی اسے ایک طرف سے مارتے ہیں کبھی دوسری طرف سے.اور اس طرح بار بار اس کو پتھر پر مارنے کے بعد کھاتے ہیں.یہی کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میںظاہر کی ہے اور بتایا ہے کہ جب ہم نے چیچک سے ان کو مار دیا تو چونکہ وہ ہزاروں ہزار تھے اس لئے مردوں کے ڈھیروں پر گروہ در گروہ اور جماعت در جماعت چیلیں اور گدھ اور کوے اور دوسرے مردار خور جانور اکٹھے ہو گئے.اور وہ بڑے بڑے جرنیل اور کرنیل جن کے اردگرد ہروقت پہرے رہتے تھے اور جو بڑی بڑی اعلیٰ وردیاں پہن کر اکڑ اکڑ کر چلتے تھے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کر اور پتھروں پر مار مار کر کھانے لگے.غالباً کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو گا جس نے اپنی زندگی میں یہ نظارہ نہ دیکھا ہو کہ چیلیںاور گدھ کس طرح بوٹی کھاتے ہیں.ہم نے تو ہزار ہا دفعہ دیکھا ہے ان کا یہی طریق ہوتا ہے کہ وہ بوٹی کو توڑ کر اینٹ یا پتھر پر جا بیٹھتے ہیں اور پھر اس بوٹی کو چونچ میں مضبوطی سے پکڑ کر پتھر پر مارتے ہیں.کبھی اس طرف سے اور کبھی اس طرف سے.شاید اس لئے کہ وہ مار مار کر اسے نرم کرنا چاہتے ہیں یا اس کی کوئی اور وجہ ہے بہرحال وہ کرتے اسی طرح ہیں.ابرہہ کا لشکر بھی جب چیچک سے مر گیا تو مردار خور جانور اکٹھے ہو گئے اور انہوںنے ان کی بوٹیاں توڑ توڑ کر اور پتھروں پر مار مار کر کھانی شروع کر دیں اس کے بعد کیا ہو االلہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ.اس نے انہیں دانہ کھائے ہوئے سٹے کی طرح کر دیا جس طرح اندر سے گندم کو کیڑا کھا جائے اور اوپر کا صرف چھلکا باقی رہ جائے.اسی طرح ان کی کیفیت ہو گئی.ان کا گوشت سب گدھیں اور چیلیں اور کوے کھا گئے اورباقی صرف ہڈیاں رہ گئیں یا چمڑا اور سر کے بال رہ گئے.یہ وہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں بیان فرمایا اور جو تمام آیات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے.افسوس ہے کہ مفسرین نے بجائے اس کے کہ حقیقت پر غور کرتے ایسے ایسے لاطائل اور بے بنیاد اور لغو قصے اس کے متعلق اپنی تفسیروں میں بھر دیئے ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کی اپنی عقل بھی حیران ہوتی ہے اور دشمن کو بھی اسلام پر ہنسی اڑانے کا موقع ملتا ہے.
Page 389
سُوْرَۃُ قُرَیْشٍ مَکِّیَّۃٌ سورۃ قریش.یہ سورۃ مکی ہے.وَ ھِیَ اَرْبَعُ اٰیَاتٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَفِیْـھَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے سوا چار آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے.سورۃ قریش کے دو نام اس سورۃ کے دو نام ہیں اسے قریش بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک نام حدیثوں میں لِاِیْلَافٍ بھی آتا ہے(بخاری کتاب التفسیر باب وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ) لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ درحقیقت تین لفظ ہیں لیکن بعض لوگ جن کو پورے معنے نہیں آتے وہ غلطی سے لِاِيْلٰفِ کو ایک اور قُرَيْشٍ کو دوسرا لفظ سمجھ لیتے ہیں.یہ تو خیر جہلاء کی بات ہے معنوں کے لحاظ سے علماء بھی اس آیت کے معنوں میں مشکلات محسوس کرتے چلے آتے ہیں.سورۃ قریش مکی سورۃ ہے مستشرقین اس سورۃ کو مکی قرار دیتے ہیں لیکن ضحاک اور کلبی دونوں نے اسے مدنی قرار دیا ہے(فتح البیان سورۃ قریش ابتدائیۃ) ابن عباسؓ کی روایت یہ ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے.چونکہ ضحاک اور کلبی دونوں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں اس لئے میرے نزدیک بھی اس کا مکی ہونا ثابت ہے کیونکہ ایک صحابی کی روایت بہرحال زیادہ صحیح مانی جائے گی.وہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ہو لازماً وہ تاریخ زیادہ صحیح طور پر بتا سکتا ہے اور بعد میں آنے والوں کی روایت اس کے مقابلہ میں بغیر دلیل کے کوئی وقعت نہیں رکھ سکتی حضرت ابن عباسؓ کی روایت سےباقی مفسرین نے بھی اتفاق کیا ہے اور مستشرقینِ یورپ بھی عام طور پر اسے مکی قرار دیتے ہیں بلکہ بعض اسے نہایت ابتدائی سورتوں میں سے سمجھتے ہیں.چنانچہ نولڈکے جرمن مستشرق اسے مکی قرار دیتا ہے اورساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ نہایت ابتدائی سورتوں میں سے ہے.نولڈکے کا خیال ہے کہ یہ سورۃ الفیل کے زمانہ کی ہے وہیری نے بھی اپنی تفسیر میں اسے مکی قرار دیا ہے.(A Coprehensive Commentary on The Quran by Wherry vol:4, page 282) ہمارے مفسرین اور مستشرقین میں یہ فرق ہے کہ مفسرین اپنے دعویٰ کی بنیاد تاریخ پر رکھتے ہیں لیکن مستشرقین بجائے تاریخ پر بنیاد رکھنے کے مضمون اور عبارت سے نتائج اخذ کرتے ہیں.مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ قرآن کریم کا
Page 390
مضمون صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ اتنی عر بی جانتے ہیں کہ اس کی عبارت سے صحیح نتائج اخذ کرنے کی قابلیت رکھتے ہوں.مشہور مستشرق مارگولیتھ تھے یہ چوٹی کے مستشرقین میں سے سمجھے جاتے تھے.عربی کے بھی یہ پروفیسر تھے اور تاریخ کے بھی پروفیسر تھے خصوصاً اسلامی تاریخ کے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے لائف بھی لکھی ہے.انہوں نے ایک دفعہ عربی بولنے کی مہارت کا دعویٰ کیا تھا میں جب لندن گیا تو لڑکوں نے شرارت سے ان کو مجبور کیا کہ وہ ہم سے عربی میں بات کریں.باوجود ہمارے عرب ممالک میں نہ رہنے اور عربی بولنے کی مہارت نہ ہونے کے (پروفیسر مارگولیتھ کئی سال مصر میں رہ چکے تھے) دو چار فقروں کے بعد مارگولیتھ صاحب کہنے لگے میں عربی میں بات نہیں کر سکتا.سو حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین عربی بہت کم جانتے ہیں.صرف بعض بعض مضامین کے بارہ میں انہوں نے تحقیق کی ہوتی ہے اور ان میں سےبعض مضامین میں وہ واقعہ میں بعض کام کی باتیں نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں.اگر عربی کتب میں سے ہم وہی باتیں خود نکالنا چاہیں تو نکال تو سکتے ہیں لیکن ہمیں بہت سی کتابیں دیکھنی پڑیں گی اور بہت زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا.مگر بہرحال زبانِ عربی سے ان کی واقفیت اتنی کم ہے کہ ان کا آیات قرآنیہ کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کی مکہ والی زبان ہے اور اس کی مدینہ والی محض ایک ڈھکوسلہ ہوتا ہے.باقی رہا ان کا زمانہ کی تاریخ کے لحاظ سے سورتوں اور آیات کی ترتیب قائم کرنا دراصل یہ ان کی ہمارے مذہب پر ایک زد ہوتی ہے اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم زمانہ کے لحاظ سے نازل ہواہے یعنی جس رنگ میں زمانہ بدلتا گیا اسی رنگ میں قرآن کریم کے احکام بھی بدلتے چلے گئے.یوں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حالات کو مدّ ِنظر رکھا ہے مگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ حالات نہ ہوتے تب بھی خدا تعالیٰ یہ احکام ضرور نازل کرتا کیونکہ یہ احکام صرف مکہ اور مدینہ کے لئے نہیں تھے بلکہ تمام دنیا کے لئے تھے.مگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حالات مکہ کے زمانہ کے مطابق ہیں اور وہ حالات مدینہ کے زمانہ کے مطابق ہیں.اس لئے فلاں فلاں سورتیں مکی ہیں اورفلاں فلاں مدنی.لیکن بہرحال چونکہ ان کا رعب دنیا پر قائم ہے اس لئے ان کا نام ہمیں لانا پڑتا ہے اور چونکہ اس زمانہ میں لوگ ان کی بات کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اس لئے ہم بھی جہاں ہمیں اپنے مفید مطلب کوئی بات نظر آتی ہے ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض جگہ مضمون بھی کسی سورۃ کے مکی یا مدنی ہونے پر دلالت کرتاہے مگر یہ کوئی مستقل دلیل نہیں ہاں بعض جگہ ایسا ضرور ہوتا ہے.چنانچہ میرے نزدیک اس سورۃ کا مضمون بھی ایسا ہے جو اس کے مکی ہونے پر دلالت کرتا ہے.اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے مکہ کی حفاظت کا وعدہ تھا ورنہ مدینہ میں جانے کے بعد تو یہ پیشگوئیاں شروع ہو گئی تھیں کہ ہم خود مکہ فتح کریں گے.اس لئے مکہ کے حالات بہرحال
Page 391
ہجرت سے پہلے زمانہ سے ہی مطابقت رکھتے ہیں.جیسا کہ میں نے بتایا ہے آخری پارہ کی سورتیں یکے بعد دیگرے اسلام کے ابتدائی اور آخری زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں یعنی ایک سورۃ اگر ابتدائے زمانۂ اسلام کے متعلق ہوتی ہے تو دوسری سورۃ آخری زمانۂ اسلام کے متعلق ہوتی ہے.یہ سورۃ اسلام کے ابتدائی زمانہ کے متعلق ہے جیسا کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ والی سورۃ آخری زمانہ کے متعلق تھی.سورۃ قریش کا سورۃالفیل سے تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت کی اور یہ کہ آئندہ زمانہ میں بھی وہ کعبہ کی اسی طرح حفاظت فرمائے گا.آئندہ زمانہ کی بات تو ابھی دنیا نے دیکھی نہیں جب وقت آئے گا دنیا اس نظارہ کو بھی دیکھ لے گی.لیکن پہلا نشان مکہ والے دیکھ چکے ہیں.اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اسی نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس عظیم الشان نشان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی مکہ کے لوگ دنیا کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف کم توجہ کرتے ہیں حالانکہ اتنا بڑا نشان دیکھنے کے بعد انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والوں اور اس کی سچی خدمت کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ خود حافظ و ناصر ہوتا ہے اور اس وجہ سے انہیں دنیا کی طرف کم توجہ کرنی چاہیے تھی مگر افسوس ہے کہ ان کی حالت اس کے برعکس ہے.دوسرا تعلق اس سورۃ کا پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں کعبہ کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا تھا.اب اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ خانۂ کعبہ سے محبت رکھنے والوں کے انجام کا ذکر کرتا ہے.گویا ایک میں دشمنوں کا انجام بتایا اور دوسری میں دوستوں سے خواہ وہ گناہ گار ہی تھے اپنے تعلق کا اظہار کیا اور ان پر اپنے احسان کا ذکر کیا.میں اوپر بتا چکا ہوں کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا اس امر کا مزید ثبوت ان دونوں سورتوں کا یکے بعد دیگرے آنا ہے.دنیا میں یہ ایک مسلّمہ اصول ہے کہ جب کسی چیز کے دونوں پہلو بیان کر دیئے جائیں اور وہ دونوں پہلوؤں سے کامل نظر آتی ہو تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ اتفاقی ہے.چونکہ اصحاب الفیل کے واقعہ پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ کیوں نہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دے دیا جائے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورۂ اِیْلٰف کے ذریعہ اس اعتراض کو دور کر دیا.پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس نے خانۂ کعبہ سے دشمنی کی اس سے ایسا ایسا سلوک ہوا.اب سورۂ اِیْلٰف میں یہ بتاتا ہے کہ جس نے خانۂ کعبہ سے دوستی کی اس سے اس اس طرح سلوک ہوا.اگر خانۂ کعبہ سے دشمنی رکھنے والوں کی سخت ذلّت اور رسوائی ہوئی اور دوسری طرف خانۂ کعبہ سے دوستی
Page 392
رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہر شخص ان دونوں متقابل باتوں کو دیکھ کر سمجھ سکتاہے کہ یہ جو کچھ ہوا بالارادہ ہوا اتفاقی امر نہیں تھا.مثلاً ہمارے ہاں پٹواری زمین کی پیمائش کرتے ہیں تو ان کا طریق یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایک پختہ نشان سے زمین کی پیمائش شروع کرتے ہیں اور مقصود زمین کے نشانات لگالیتے ہیں اس کے بعد ایک اورپختہ نشان سے پیمائش شروع کرتے ہیں اورپھر اس کے مطابق اس زمین کا حدود اربعہ نکال لیتے ہیں.اگر دونوں اطراف کی پیمائش آپس میں مطابق ہو جائے تو اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا اور تسلّی ہو جاتی ہے کہ جو حد قائم کی گئی ہے وہ بالکل درست ہے.اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک سورۃ میں یہ بیان کیا کہ دشمن سے کیا معاملہ ہوا اور دوسری سورۃ میں یہ بیان کیا کہ دوست سے کیا معاملہ ہوا.جب ایک طرف اس سلوک کا ذکر کیا گیا ہے جو خانۂ کعبہ کے دشمنوں سے ہوا اور دوسری طرف اس سلوک کا ذکر کیا گیا ہے جو خانۂ کعبہ کے دوستوں سے ہوا تو جس طرح پٹواری جب دونوں طرف سے پیمائش کر لیتا ہے تو اس کی قائم کردہ حدود قطعی طور پر درست ہوتی ہیں اسی طرح دوست اور دشمن سے مقابل کا یہ سلوک بتاتا ہے کہ دشمن سے جو سلوک ہوا وہ بھی بالارادہ تھا اور دوست سے جو سلوک ہوا وہ بھی بالارادہ تھا اور چونکہ دونوں زاویوں سے پیمائش ایک ہی نکلی ہے.اس لئے دشمن کی تباہی اتفاقی امر نہیں کہلا سکتا.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ (تعالیٰ) کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا(اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍۙ۰۰۲ (اور اغراض کے علاوہ) قریش کے دلوں کو مانوس کرنے کے لئے، اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِۚ۰۰۳ یعنی ان کے دلوں کو گرمائی اور سرمائی سفروں سے مانوس کرنے کے لئے (ہم نے ابرہہ کو تباہ کیا) حلّ لُغات.لِاِیْلٰف.لِاِیْلٰف میں جو لام آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی متعلق محذوف ہے.عربی زبان میں حروف کے ساتھ کلمے شروع نہیں ہوا کرتے بلکہ یا تو فعل سے کلمہ شروع ہوتا ہے یا اسم سے شروع ہوتا ہے.مثلاً کہیں گے ذَھَبَ زَیْدٌ زید گیا یا کہیں گے زَیْدٌ ذَاھِبٌ زید جانے والا ہے.پس عربی زبان میں یا تو فعل
Page 393
کے ساتھ جملہ شروع ہوتا ہے یا اسم کے ساتھ.اسم کے ساتھ اگر جملہ شروع ہو گا تو وہ مبتداء اور خبر سے مرکب ہو گا اور اگر فعل کے ساتھ جملہ شروع ہو گا تو وہ فعل اور فاعل سے مرکب ہو گا حرف کے ساتھ کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا.مثلاً یہاں لام حرف ہے اور اِیْلٰــــفٌ مصدر ہے اس کو دیکھ کر ہر شخص جو معمولی عربی بھی جاننے والا ہو فورًا سمجھ جائے گا کہ اس فقرہ سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ محذوف ہے کیونکہ نہ تو یہ جملہ فعل کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور نہ اسم کے ساتھ نہ یہ مبتداء اور خبر ہے نہ فعل اور فاعل ہے.اس لئے لام کا متعلق بہرحال یہاں محذوف ہے.حروف کے متعلق عربی زبان میں یہ طریق رائج ہے کہ اگر کسی فقرہ کے شروع میں وہ آجائیں تو ان کا متعلق محذوف ہوتا ہے مثلاً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ کو ہی لے لو.یہ باء سے شروع ہوتی ہے جو ایک حرف ہے اس لئے اس سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ محذوف ہے جو باء کا متعلق کہلاتا ہے اور وہ محذوف یہ ہے کہ اَقْرَأُ یا اَشْـرَعُ یعنی میں اللہ کا نام لے کر پڑھتا ہوں یا اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں یا اِقْرَأْ یا اِشْـرَعْ (روح المعانی سور ۃ الفاتحۃ).اسی طرح لِاِیْلٰف میں بھی لام کا متعلق محذوف ہے.اگر کوئی کہے کہ آپ کو کس طرح پتہ لگ گیا کہ اس سے پہلے ضرور کچھ محذوف ہے کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ محض ایک ڈھکوسلہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ڈھکوسلے کا کوئی سوال نہیں عربی لغت نے ایک قاعدہ بنایا ہوا ہے اس کے ماتحت ہم خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں کا متعلق محذوف ہے یا نہیں.یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی ڈاک خانہ میں تار دینے جائےاور ٹِک ٹِک کی آواز سنے تو پوچھے کہ آپ لوگوں کو کس طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ اس ٹِک ٹِک سے مراد کیا ہے تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ گورنمنٹ نے پہلے سے ایک کوڈ بنایا ہوا ہے اس کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے جب ٹِک کی آواز آتی ہے تو ہم فورًا سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے A مراد ہے یا Bمراد ہے یا C مراد ہے.اسی طرح عربی زبان میں تمام قواعد مدوّن ہیں ان کے مطابق جب کسی فقرہ سے پہلے حرف آئے گا مثلاً باء آئے گی یا لام آئے گا تو ہم ان قواعد کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے فوراً سمجھ جائیں گے کہ ان کا متعلق محذوف ہے.بےشک بعض دفعہ دو دو چار چار متعلق بھی نکل آئیں گے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرف تو شروع میں آئے مگر اس کا متعلق محذوف نہ ہو.یہاں بھی لِاِیْلٰف کے لام نے بتا دیا ہے کہ اس کا متعلق محذوف ہے.اب رہا یہ سوال کہ کیا محذوف ہے؟ اس بارہ میں بہت کچھ اختلاف ہے مگر اس اختلاف کے معنے صرف اتنے ہیں کہ کسی کا رجحان کسی معنے کی طرف چلا گیا ہے اور کسی کا رجحان کسی طرف.اور چونکہ وہ معنے سب کے سب اس مقام پر چسپاں ہو جاتے ہیں اس لئے ہمارے نزدیک جھگڑے یا اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے درست ہیں.کئی متعلق ہونے کے یہ معنے نہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو ہی درست قرار دیں اور باقی متعلقات
Page 394
کو رد کر دیں.بلکہ اگر سارے کے سارے متعلق معنوں کے لحاظ سے چسپاں ہو جاتے ہیں تو ہم ان سب کو تسلیم کر لیں گے صرف یہ کہیں گے کہ کسی نحوی عالم کا ذہن ایک طرف چلا گیا ہے اور کسی نحوی عالم کا ذہن دوسری طرف چلا گیا ہے.اس لحاظ سے خواہ دو متعلق ہوں یا تین ہوں یا چار ہوں اگر وہ سب کے سب اپنے معانی کے لحاظ سے آیت پر چسپاں ہو جاتے ہوں تو وہ سب کے سب درست ہوں گے.اس آیت کے محذوف کے متعلق ایک قول بصری نحویوں کا ہے اور ایک کوفی نحویوں کا.گذشتہ زمانہ میں عرب میں دو بڑے مشہور نحوی سکول تھے ایک بصری اور دوسرا کوفی.یعنی ان دونوں شہروں کے نحوی بعض الگ الگ اصول کے معتقد تھے (اسے بھی انگریزی زبان میں سکول کہتے ہیں اس سے مدرسہ مراد نہیں) اور ان اصولی مسائل کی وجہ سے ان کے مسائل کے استخراج میں فرق ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے بعض بعض مسائل نحویہ میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے.ہندوستان میں باوجود اس کے کہ مذہباً اس کے افراد زیادہ تر کوفی ہیں یعنی امام ابوحنیفہ صاحبؒ کوفی کے متبع،نحو میں زیادہ تر بصری علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے لیکن مصر اور شام کے لوگ کوفی نحویوں کے قول کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں حالانکہ وہ مذہباً شافعی ہیں.یوں اختلاف تو ہر جگہ ہے ہندوستان میں بھی اور باہر بھی.کوئی کسی نحوی کے قول کو ترجیح دیتا ہے اور کوئی کسی کے قول کو.اس تمہید کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں کہ بصری نحویوں کا قول اس بارہ میں یہ ہے کہ یہاں لام کا متعلق پہلی سورۃ کی آخری آیت ہے یعنی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.ہم نے ان کو دانہ کھائے ہوئے سِٹے کی طرح کر دیا قریش کے اِیْلَاف کے لئے.یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ہی لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍکا متعلق ہے تو خانۂ کعبہ کی حفاظت خانۂ کعبہ کی وجہ سے تھی یا ایلاف قریش کی وجہ سے؟ اگر قریش کا ایلاف مدّ ِنظر نہ ہوتا تو کیا اصحابِ فیل کو تباہ نہ کیا جاتا اگر کیا جاتاتو یہ مزید احسان قریش پر کیسا؟ گویا یہ متعلق تسلیم کرنے کی وجہ سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پہلی سورۃ میں یہ بتایا گیا تھا کہ خانۂ کعبہ کے احترام کے نتیجہ میں ہم نے ایسا کیا مگر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قریش کے اندر مودّت اور انس پیدا کرنے کے لئے ہم نے ایسا کیا.بظاہر یہ اختلاف معلوم ہوتا ہے بلکہ جو معنے میں نے بیان کئے تھے ان کے لحاظ سے تو یہ اعتراض اور بھی پختہ ہو جاتا ہے.کیونکہ میں نے صرف یہی نہیں بیان کیا تھا کہ خانۂ کعبہ کے احترام کی وجہ سے اصحابِ فیل کو تباہ کیا گیا بلکہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے بھی اصحابِ فیل کو تباہ کیا گیا.گویا پہلے تو اصحابِ فیل کی تباہی کی صرف دو اغراض بتائی گئی تھیں.(۱) خانۂ کعبہ کا
Page 395
احترام اور (۲) قریش کا ایلاف.مگر میں نے ایک تیسری وجہ بھی بتا دی جو میرے نزدیک ان دونوں وجوہ سے مقدّم اور زیادہ اہم تھی.پس یہ اعتراض اور بھی بڑھ گیا کہ پہلے دو وجوہ بتائی گئی تھیں مگر اب اسی کام کی ایک تیسری وجہ بھی بتائی جارہی ہے.مگر حقیقت یہ ہے کہ میرے معنوں کی وجہ سے یہ اعتراض زیادہ پختہ نہیں ہو گیا بلکہ بالکل مٹ گیا ہے.وجہ یہ کہ میں نے اصحاب فیل کی تباہی کی دو۲ وجوہ بتائی تھیں میں نے کہا تھا کہ پہلی سورۃ میں ایک تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا ذکر ہے اور ایک خانۂ کعبہ کے احترام کا ذکر ہے.پس جب تعدّد جائز ہو گیا تو جہاں ایک کام کی دو غرضیں ہو سکتی ہیں وہاں تیسری غرض بھی ہو سکتی ہے.میرے معنوں سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ایک کام دو اغراض کے لئے بھی ہو سکتا ہے.جب ایک کام دو اغراض کے لئے ہو سکتا ہے تو ایک کام تین اغراض کے لئے بھی ہو سکتا ہے.فرض کرو ایک شخص لائل پور سے چلا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ راولپنڈی سے سودا خریدے مگر پھر اسے خیال آتا ہے کہ چلو پشاور چلوں وہاں میرے بعض رشتہ دار رہتے ہیں اس طرح دونوں کام ہو جائیں گے.پشاور سے میں سودا بھی خرید لوں گا اور اپنے رشتہ داروں سے بھی مل لوں گا.تو یہ تعدّدِ اغراض بالکل درست ہو گا.اسی طرح اللہ تعالیٰ خانۂ کعبہ کا احترام بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے بلکہ میرے نزدیک مقدّم غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ظاہر کرنا تھی.اب اس نے ایک تیسری غرض بھی بیان کر دی ہے کہ ہم نے یہ نشان اِيْلٰفِ قُرَيْشٍ کے لئے بھی ظاہر کیا تھا اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں.جس طرح ایک ہی سفر کی تین غرضیں بھی ہوسکتی ہیں سودا بھی خرید لیا جائے، رشتہ داروں سے بھی مل لیا جائے اور کسی دوست سے بھی ملاقات کرلی جائے اسی طرح اصحابِ فیل کی تباہی بھی تین اغراض کے لئے ہو سکتی ہے.جب دنیوی کاموں میں تعدّدِ اغراض کو جائز سمجھا جاتا ہے جائز ہی نہیں بلکہ بعض دفعہ مستحسن خیال کیاجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اگر ایک کام کی تین اغراض بتادیں تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا.پس لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ کے جو معنے بصری نحویوں نے کئے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا.اصحابِ فیل کی تباہی سورۂ فیل کی بتائی ہوئی اغراض کے علاوہ قریش کی دلجمعی اور تسلّی کے لئے بھی ہو سکتی تھی اور یہ سورۃ بتاتی ہے کہ اس تباہی میں یہ غرض بھی مخفی تھی.بعض لوگ تعدّد اغراض کے خلاف فلسفیانہ رنگ میں اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کام کی اگر کئی اغراض ہوں تو ان میں سے کوئی مقدّم اور اہم ہو گی اور جب کوئی غرض اہم اور مقدّم ہو گی تو باقی سب ضمنی رہ جائیں گی مقصود ان میں سے کوئی بھی نہ ہو گی.اس کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے کہ خالص فلسفہ ایک لغو اور بے ہودہ شے ہے جو محض کتابوں تک محدود ہوتا ہے ورنہ دنیا میں تمام باتیں ہوتی ہیں.دیکھنا یہ نہیں کہ فلسفی کیا کہتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کیا
Page 396
کرتی ہے.اگریہی فلسفہ کسی کے سامنے بیان کرو اور کہو کہ تو نے کہا تھا میں شادی اس لئے کر رہا ہوں کہ گھر بس جائے گا اولاد ہو گی اور اب تو کہتا ہے کہ روٹی کا بھی آرام ہو جائے گا ان دونوں میں سے تمہاری کوئی ایک ہی غرض ہو سکتی ہے دونوں نہیں تو وہ کیا کہے گا، وہ ایسا اعتراض کرنے والے کو پاگل سمجھے گا بلکہ شادی کی ایک تیسری غرض بھی ہوتی ہے کہ تقویٰ حاصل ہو کیونکہ شہوانی قویٰ بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں پیدا کئے ہوئے ہیں.پھر بعض لوگ جن کی طبیعت میں کچھ نقص ہوتا ہے وہ تو یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی پڑھا ہوا نہیں لڑکی پڑھی ہوئی ہے اگر وہ آئی تو ہمارے گھر میں بھی علم کا چرچا ہو جائے گا.اس طرح شادی کی ایک اور غرض بھی بیان کر دی جاتی ہے اور کوئی شخص نہیں کہتا کہ تم ایک ہی کام کی تین تین چار چار اغراض بیان کر رہے ہو یہ تو درست نہیں صرف ایک غرض ہونی چاہیے.پس فلسفی کا یہ کہنا کہ ایک غرض اصلی ہو گی اور باقی سب ضمنی ہوں گی بالکل غلط ہے.حقائق کا علم علم النفس اور فلسفہ کے امتزاج سے ہوتا ہے محض فلسفہ سے نہیں.اگر ہم سب امور کا تجزیہ فلسفہ سے کریں تو دنیا کی کوئی حقیقت حقیقت نہیں رہتی.دنیا کے بہت سے کام کئی کئی اغراض کے لئے ہوتے ہیں.یہ بھی ہوسکتا ہے کہ صرف ایک غرض کے لئے وہ کام نہ کیا جاتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر صرف ایک غرض ہوتی تب بھی وہ کر لیا جاتا.پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب اغراض ایک اہمیت کی ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کم و بیش اہمیت کی ہوں.یہ بھی ممکن ہے کہ کم اہمیت والی اغراض خالی ہوتیں تو ان کے لئے کام نہ کیا جاتا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر وہی ہوتیں زیادہ اہمیت والی شے نہ ہوتی تو بھی کام کیا جاتا.بہرحال ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وجہ مقدّم ہے اور کوئی مؤخر.مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعدّدِ اغراض ناجائز ہے.ایسا کہنا فطرتِ انسانی کے بھی خلاف ہے اور واقعات کے بھی خلاف ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کے بھی خلاف ہے.کیونکہ فطرتِ انسانی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے مطابق پیدا کی ہے.ہم اپنی فطرت پر قیاس کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات بھی اسی رنگ میں جاری ہوتی ہیں.اور صرف صفاتِ الٰہی پر غور کر کے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے.بعض لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر فرض کرو ایک ہی غرض ہوتی تو کیا وہ شخص کام کرتا یا نہ کرتا؟ ہم کہتے ہیں ضرور کرتا.اس پر وہ کہتے ہیں تو پھر تم اور اغراض اس کےساتھ کیوں شامل کرتے ہو.ہمارا جواب یہ ہے کہ اس امر کا فیصلہ کہ وہ کام کس غرض سے تھا کام کرنے والے کے بیان پر منحصر ہے.اگر اس نے ایک کام دو۲ اغراض سے کیا ہے اور وہ دو۲ اغراض منطقی طور پر اس کام کی غرض بن سکتی ہیں توبہرحال ہمیں اس کی بات کو تسلیم کرنا ہو گا اور اس پر اعتراض کرنے والا بے وقوف ہو گا.ہمارا کوئی حق نہیں ہو گا کہ ہم کہیں کہ صرف فلاں غرض اس کام کی تھی باقی سب غرضیں باطل ہیں.
Page 397
اس تمہید کے سمجھ لینے کے بعد یہ امر سمجھ لینا آسان ہے کہ اصحابِ فیل کی تباہی تینوں اغراض کے لئے تھی اور یہ کہنا کہ اگر یہ تباہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام یا خانۂ کعبہ کے بچانے کے لئے تھی تو قریش پر احسان کیوں جتایا گیا ہے باطل اور واقعات کے خلاف ہے.جب اس تباہی کی تینوں اغراض تھیں تو وہ ان تینوں کا ذکر کرے گا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا بھی ذکر کرے گا، خانۂ کعبہ کی عزت کا بھی ذکر کرے گا اور قریش پر احسان بھی جتائے گا.دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر کام کئی طرح پورا کیا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک طرح پورا کرنے میں ایک غرض پوری ہو اور دوسری طرح پورا کرنے میں دو غرضیں پوری ہوں.پس اگر اس کام کو دوسری طرح پورا کیا گیا ہے تو اس کے صاف معنے یہ ہیں کہ دونوں اغراض مدّ ِنظر تھیں اور اگر تیسری طرح پورا کیا گیا ہے جس کے ساتھ تین اغراض وابستہ تھیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ تینوں اغراض اس کے مدّ ِنظر تھیں.میں اوپر تفصیلاً بتا چکا ہوں کہ ابرہہ اور اس کے لشکر اور اس کی حکومت کی تباہی صرف خانۂ کعبہ کے احترام اور اس کی عزت کی حفاظت کے لئے نہیں تھی کیونکہ جتنی تباہی سے خانۂ کعبہ بچ سکتاتھا اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی جو بتاتی ہے کہ اس کی تباہی میں کچھ اور اغراض بھی تھیں.مثلاً خانۂ کعبہ کی حفاظت اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ ابرہہ کے لشکر میں چند موت کے حادثات ہو جاتے اور وہ ڈر کر بھاگ جاتے.اس طرح بھی خانۂ کعبہ اس کے حملہ سے بچ سکتا تھا لیکن اگر مسیحی حکومت یمن سے بالکل برباد نہ ہو جاتی تو اس کی طرف سے مکہ پر بار بار حملے ہوتے رہتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقی نہ کر سکتے.ادھر یہ جو ذکر ہے کہ قریش یمن کا سفر کیا کرتے تھے وہ بھی نہ کر سکتے.آخر جس ملک سے لڑائی ہو اس کی طرف وہ آزادانہ رنگ میں کس طرح سفر کر سکتے تھے.پس اللہ تعالیٰ نے صرف ابرہہ اور اس کے لشکر کو نہیں بھگایا بلکہ یمن سے اس کی حکومت ہی مٹا دی اسی تباہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے پچھلی سورۃ میں اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ غور کرو اور سوچو کہ ہم نے اصحابِ فیل کو کس رنگ میں تباہ کیا اور دیکھو کہ اس سے نہ صرف مکہ بچ گیا بلکہ یمن سے عیسائی حکومت بھی اٹھ گئی اور یمن کی عیسائی حکومت کے تباہ ہونے کی وجہ سے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن نے مکہ میں ترقی کی اور اس تباہی کی وجہ سے ہی قریش کو یمن میں سردی کا سفر نصیب ہوا.اگر یہ تباہی نہ ہوتی تو وہ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ کس طرح کر سکتے وہاں تو ان کا دشمن بیٹھا ہوا تھا.یہ تمام امور بتاتے ہیں کہ خالی ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی اللہ تعالیٰ کے مدّ ِنظر نہیں تھی بلکہ یہ ایک ایسی صورت پیدا کی جارہی تھی جس کے نتیجہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی ہو جاتی، خانۂ کعبہ کی بھی حفاظت ہو جاتی اور مکہ والوں کے
Page 398
سفروں میں بھی روک پیدا نہ ہوتی.پس تباہی کی کیفیت اس نوع کی تھی کہ وہ کیفیت صاف طور پر ایلافِ قریش کی غرض کو بھی ثابت کرتی ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ نبیٔ عربیؐ کی بننے والی امت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے مدّ ِنظر تھی کیونکہ اس کی حفاظت میں نبیٔ اُمّیؐ کی بعثت کی کامیابی مضمر تھی.پس مکہ والوں کی حفاظت بحیثیت مکہ والوں کے نہیں کی گئی یا قریش کی حفاظت بحیثیت قریش کے نہیں کی گئی بلکہ قریش کی اگر حفاظت کی گئی تو اس لئے کہ قریش آئندہ آنے والے نبیٔ اُمّیؐ کی اُمّت بننے والے تھے.اگر وہ پراگندہ ہو جاتے تو وہ اس کی اُمّت نہ بن سکتے.پس مکہ والوں کی حفاظت بھی مکہ والوں کی خاطر نہیں تھی بلکہ وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھی گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کی خاطر اس قوم کو بھی بچایا گیا.خلاصہ یہ کہ اصحابِ فیل کو مندرجۂ ذیل تین اغراض کے پورا کرنے کے لئے تباہ کیا گیا.اصحاب فیل کو تباہ کئے جانے کی تین اغراض اوّل.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لئے.دوم.خانۂ کعبہ کے اعزاز کے لئے.سوم.قریش کو بچانے کے لئے جو حاملِ دینِ مصطفویؐ ہونے والے تھے نہ کہ ان کی کسی ذاتی خوبی کی وجہ سے.کیا سورۃ قریش سورۃ فیل کا حصہ ہے؟ اس جگہ ایک اور سوال کا حل کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ میں لام کا جو تعلق پہلی سورۃ سے ظاہر کیا گیا ہے اس سے یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ سورۃ سورۃ الفیل کا ایک حصہ ہی ہے علیحدہ سورۃ نہیں.اس کے متعلق بعض علماء نے یہ مزید دلیل دی ہے کہ ابی ابن کعب کے نسخۂ قرآن میں اس سورۃ اور اصحاب الفیل کی سورۃ کو اکٹھا لکھا ہوا ہے اور دوسری تائیدی دلیل یہ پیش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پہلی رکعت میں سورہ ٔ تین پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۂ فیل اور سورۂ قریش دونوں پڑھیں اور بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھی(کشاف زیر آیت ھذا).اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی یہ دونوں سورتیں ایک ہی تھیں لیکن یہ دلائل کوئی قوت نہیں رکھتے.ابی ابن کعب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان چار آدمیوںمیں سے تھے جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قُرّاءِ اُمّت ہیں اگر کسی شخص نے قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھے(بخاری کتاب فضائل القراٰن باب القراء من اصحاب رسول اللہ).لیکن جہاں یہ درست ہے وہاں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ابی ابن کعب ویسے ہی غلطی کر سکتے ہیں جیسے کوئی اور شخص غلطی کر سکتا ہے.ہم اپنے پاس سے ایک مضمون بنا کر لکھتے ہیں لیکن
Page 399
اس میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہیں ’’ہے‘‘ رہ جاتا ہے، کہیں کا کی جگہ ’’کی‘‘ لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں کوئی اور غلطی ہوجاتی ہے.کاتب قرآن کریم لکھتے ہیں تو باوجود اس کے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے مشّاق کاتب ہوتے ہیں پھر بھی ان سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں.اسی طرح ممکن ہے کسی جگہ پر غلطی سے ابی ابن کعب کو خیال نہ رہا ہو اور وہ ان دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ لکھنا بھول گئے ہوں.جبکہ قرآن کریم کاجو نسخہ ہمارے پاس ہے اس میں ان دونوں سورتوں کو الگ الگ لکھا ہوا ہے اور ان کے درمیان بسم اللہ بھی لکھا ہوا ہےا ور قرآن کریم کا یہ نسخہ ایسا ہے جس کی ترتیب میں صرف ابی ابن کعب نے ہی کام نہیں کیا بلکہ بہت سے اور صحابہ نے بھی جن کا رتبہ قرأت میں حضرت ابی بن کعب سے کم نہ تھا کام کیا تھا.چاروں قُرّاء نے مل کر اس میں حصہ لیا ہے اور باقی سارے صحابہؓ نے بھی مل کر حصہ لیا ہے.جو نسخہ ان ساروں نے مل کر لکھا ہے یہ صاف بات ہے کہ وہ زیادہ احتیاط سے لکھا ہوا ہو گا.پھر ابی ابن کعب کے نسخہ میں تو غلطی کا امکان ہے کیونکہ کسی نے اس پر بحث نہیں کی لیکن اس پر بحثیں کی گئی ہیں اور صحابہؓ نے اس کے متعلق اپنی شہادتیں اور گواہیاں دی ہیں.کوئی سورۃ نہیں لکھی گئی، کوئی آیت نہیں لکھی گئی، کوئی زیر اور زبر نہیں لکھی گئی جس کے متعلق دو قسم کی شہادتیں نہیں لی گئیں.ایک یہ کہ تحریر موجود ہو.دوسرے یہ کہ زبانی گواہ موجود ہوں جو یہ کہتے ہوں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے.یہ کتنی بڑی محنت ہے اور کتنی بڑی احتیاط کا ثبوت ہے.زبانی گواہی کو نہیں مانا گیا جب تک اس کے ساتھ تحریری شہادت نہ ہو اور تحریری شہادت کو نہیں مانا گیا جب تک اس کے ساتھ زبانی گواہ نہ ہوں.گویا تحریر بھی موجود ہو اور زبانی گواہ بھی موجود ہوں تب کسی سورۃ یا آیت کو قرآن کریم میں شامل کیا جاتا اور یہ زبانی گواہ بھی بعض دفعہ سینکڑوں تک ہوا کرتے تھے صرف ایک دو آیتیں ایسی ہیں جن کے متعلق صرف دو دو گواہ ایسے ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے.(بخاری کتاب فضائل القراٰن باب کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم )لیکن باقی ساری آیتیں اور سورتیں ایسی ہیں جن میں کسی کے بیس، کسی کے پچاس اور کسی کے سو گواہ تھے اور بہت سے حصوں کے ہزاروں گواہ موجود تھے.بہرحال وہ شہادت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سے ثابت ہوتی تھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے املاء اور لکھوانے سے ثابت ہوتی تھی.پھر زبانی گواہ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنایا ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پڑھا ہے وہی قطعی اور یقینی سمجھی جاتی تھی اور اسی قسم کی شہادتوں کے بعد ہی قرآن کریم میں کوئی آیت شامل کی جاتی تھی.پس وہ نسخۂ قرآن جو ہمارے پاس ہے اور جس میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کو الگ الگ لکھا ہو اہے.یہ خود اپنی ذات میں اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ یہ دونوں سورتیں الگ الگ ہیں.اگر ایک شخص
Page 400
اپنے طور پر قرآن کریم لکھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دو سورتوں کے درمیان بسم اللہ اس سے غلطی سے رہ جائے.پس یہ کوئی دلیل نہیں جو پیش کی گئی ہے.دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اس منفی دلیل کے علاوہ ایسی مثبت دلیل بھی موجود ہے کہ سورۃ قریش سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اس کے الگ سورۃ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور وہ یہ ہے کہ تمام مؤرخین اور تمام قُرّاء اور تمام ماہرین فن صحابہؓ سے متفقہ طو رپر یہ بات ثابت ہے کہ صرف ایک سورۃ البراءۃ ایسی ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اس شہادت کے دینے والوں میں خود ابی ابن کعب بھی شامل ہیں.یہ سب گواہ اتفاق کرتے ہیں کہ سوائے سورۃ البراءۃ کے اور کوئی سورۃ نہیں جس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی نہ ہو.اور جب سوائے سورۃ البراءۃ کے سارے قرآن کریم میں اور کوئی سورۃ نہیں جس سے پہلے بسم اللہ نہ ہوتو اگر ابی ابن کعب نے اپنے نسخۂ قرآن میں سورۃ قریش سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی تو یہ بات خود تواتر کے خلاف ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی.احادیث صحیحہ سے صاف ثابت ہے کہ جس سورۃ سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ لکھواتے تھے وہ اس کے ایک الگ سورۃ ہونے کی ایک قطعی شہادت ہوتی تھی.یہی وجہ ہے کہ سورۃ البراءۃ کے متعلق یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ کوئی الگ سورۃ ہے یا نہیں.حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کا یہی خیال تھا کہ یہ سورۃ الگ نہیں بلکہ یہ ایک فصل ہے سورۂ انفال کے مضمون کی(حقائق الفرقان زیر تفسیر سورۃ توبہ آیت ۱).اور میرے نزدیک یہی درست ہے میں غور سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ سورۂ انفال میں ایک دعویٰ کیا گیا ہے جس کا تفصیلی ثبوت سورۃ البراءۃ میں پیش کیا گیا ہے.چونکہ یہ مضمون مستقل اور اہم تھا اس لئے اس کو بطور فصل قرار دے دیا گیا.پس وہ کوئی الگ سورۃ نہیں بلکہ سورۂ انفال کی ہی ایک فصل ہے اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ صریح طور پر حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نئی سورۃ لکھواتے اس سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ضرور لکھواتے تھے.سورۃ البراءۃ سے پہلے چونکہ بسم اللہ نہیں اس لئے یہ سورۃ الانفال سے کوئی الگ سورۃ نہیں مگر چونکہ یہ الگ فصل تھی مسلمانوں نے اس کا نام سورۃ البراءۃ رکھ لیا.مفسرین نے اس جگہ پر یہ بھی جواب دیا ہے کہ مضمون کا اتحاد ایک سورۃ ہونے پر دلالت نہیں کرتا اور یہ بالکل درست ہے.اس لئے کہ قرآن کریم تو سارے کا سارا منظم، سارے کا سارا مرتب اور سارے کا سارا باترتیب ہے.اس کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پروئے ہوئے ہیں جس طرح ہار میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں اور جب سارا قرآن ہی منظم ہے تو یہ کہہ دینا کہ چونکہ اس سورۃ کا مضمون لام کے ذریعہ سے پہلی سورۃ کے ساتھ
Page 401
ان معنوں پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوْا سے پہلے فاء پڑی ہوئی ہے اور فاء ہمیشہ جملہ کے آخری حصہ کے لئے آتی ہے حالانکہ لام کا متعلق پہلے آنا چاہیے تھا.وہ کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک چیز مقام کے لحاظ سے پہلے ہوتی ہے لیکن ذکر کے لحاظ سے پیچھے آتی ہے مگر فاء بتا رہی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوْا کا مقام بعدکا ہے اس لئے اسے لام کا متعلق کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے جس کا مقدم ہونا ذکراً نہ ہو تو مقاماً اور معناً ضروری ہے اس کا جواب زجاج اور زمخشری نے یہ دیا ہے کہ فاء شرط کے جواب کے لئے آتی ہے(کشاف زیر آیت ھذا) اور اس جگہ فاء سے پہلے ایک اور جملہ محذوف ہے اور یہ فاء اسی محذوف جملہ پر دلالت کرتی ہے نہ کہ اٖلٰفِهِمْ پر.چنانچہ وہ یہ فقرہ اس جگہ محذوف بتاتے ہیں فَاِنْ لَّمْ یَعْبُدُوْا بِنِعْمَۃٍ اُخْرٰی فَلْیَعْبُدُوْا رَبَّ ہٰذَا الْبَیْتِ لِاِیْلٰفِ قُرَیْشٍ.یعنی اگر خدا تعالیٰ کی اور نعمتوں کی قریش کو قدر نہیں تو کم سے کم قریش کے دلوں میں جو اس نے سردی گرمی کے سفروں کی محبت پیدا کی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.گویا اصل عبارت یوں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اگر وہ کسی اورنعمت کی قدر نہیں کرتے تو ایلافِ قریش کی نعمت کی وجہ سے ہی خدا تعالیٰ کی عبادت کریں.اِیْلٰف.لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اِیْلٰف.اٰلَفَ کا مصدر ہے اور اس کے معنے کسی چیز کی محبت دل میں ڈالنے کے ہوتے ہیں.مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں اٰلَفَ کے دو مصدر آتے ہیں اِلَافٌ بھی اور اِیْلٰــــفٌ بھی.وہ اٰلَفَ جس کا مصدر اِلَافٌ ہوتا ہے اس کے اور معنے ہوتے ہیں اور وہ اٰلَفَ جس کا مصدر اِیْلٰــــفٌ ہوتا ہے اس کے اور معنے ہوتے ہیں.جب صرف اٰلَفَ کا فعل آئے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے کیا معنے ہیں.آیا اِیْلٰــــفٌ والے معنے ہیں یا اِلَافٌ والے معنے ہیں.ہم عبارت کو دیکھ کر اس بارہ میں کوئی رائے قائم کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اٰلَفَ اِیْلٰــــفٌ والا ہے یا اٰلَفَ اِلَافٌ والا ہے.لیکن اگر مصدر ساتھ آجائے تو ہمیں اس کے معنوں کی تعیین میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی ہم فوراً سمجھ سکیں گے کہ اس کے کیا معنے ہیں.چونکہ اس آیت میں مصدر اِلَافٌ نہیں بلکہ.اِیْلٰــــفٌ استعمال کیا گیا ہے اور.اِیْلٰــــفٌ کے معنے کسی چیز کی محبت پیدا کرنےاور ڈالنے کے ہوتے ہیں خصوصاً مکان یا مقام کی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لئے اس جگہ محبت پیدا کرنے کے معنے ہی مراد لئے جائیں گے.لفظ اِیْلٰف کے متعلق پہلے مفسرین کی ٹھوکر عجیب بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے عالم بھی
Page 402
ان معنوں پر بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوْا سے پہلے فاء پڑی ہوئی ہے اور فاء ہمیشہ جملہ کے آخری حصہ کے لئے آتی ہے حالانکہ لام کا متعلق پہلے آنا چاہیے تھا.وہ کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک چیز مقام کے لحاظ سے پہلے ہوتی ہے لیکن ذکر کے لحاظ سے پیچھے آتی ہے مگر فاء بتا رہی ہے کہ فَلْيَعْبُدُوْا کا مقام بعدکا ہے اس لئے اسے لام کا متعلق کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے جس کا مقدم ہونا ذکراً نہ ہو تو مقاماً اور معناً ضروری ہے اس کا جواب زجاج اور زمخشری نے یہ دیا ہے کہ فاء شرط کے جواب کے لئے آتی ہے(کشاف زیر آیت ھذا) اور اس جگہ فاء سے پہلے ایک اور جملہ محذوف ہے اور یہ فاء اسی محذوف جملہ پر دلالت کرتی ہے نہ کہ اٖلٰفِهِمْ پر.چنانچہ وہ یہ فقرہ اس جگہ محذوف بتاتے ہیں فَاِنْ لَّمْ یَعْبُدُوْا بِنِعْمَۃٍ اُخْرٰی فَلْیَعْبُدُوْا رَبَّ ہٰذَا الْبَیْتِ لِاِیْلٰفِ قُرَیْشٍ.یعنی اگر خدا تعالیٰ کی اور نعمتوں کی قریش کو قدر نہیں تو کم سے کم قریش کے دلوں میں جو اس نے سردی گرمی کے سفروں کی محبت پیدا کی ہے اس کی قدر کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.گویا اصل عبارت یوں ہے کہ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اگر وہ کسی اورنعمت کی قدر نہیں کرتے تو ایلافِ قریش کی نعمت کی وجہ سے ہی خدا تعالیٰ کی عبادت کریں.اِیْلٰف.لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اِیْلٰف.اٰلَفَ کا مصدر ہے اور اس کے معنے کسی چیز کی محبت دل میں ڈالنے کے ہوتے ہیں.مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں اٰلَفَ کے دو مصدر آتے ہیں اِلَافٌ بھی اور اِیْلٰــــفٌ بھی.وہ اٰلَفَ جس کا مصدر اِلَافٌ ہوتا ہے اس کے اور معنے ہوتے ہیں اور وہ اٰلَفَ جس کا مصدر اِیْلٰــــفٌ ہوتا ہے اس کے اور معنے ہوتے ہیں.جب صرف اٰلَفَ کا فعل آئے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے کیا معنے ہیں.آیا اِیْلٰــــفٌ والے معنے ہیں یا اِلَافٌ والے معنے ہیں.ہم عبارت کو دیکھ کر اس بارہ میں کوئی رائے قائم کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اٰلَفَ اِیْلٰــــفٌ والا ہے یا اٰلَفَ اِلَافٌ والا ہے.لیکن اگر مصدر ساتھ آجائے تو ہمیں اس کے معنوں کی تعیین میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی ہم فوراً سمجھ سکیں گے کہ اس کے کیا معنے ہیں.چونکہ اس آیت میں مصدر اِلَافٌ نہیں بلکہ.اِیْلٰــــفٌ استعمال کیا گیا ہے اور.اِیْلٰــــفٌ کے معنے کسی چیز کی محبت پیدا کرنےاور ڈالنے کے ہوتے ہیں خصوصاً مکان یا مقام کی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس لئے اس جگہ محبت پیدا کرنے کے معنے ہی مراد لئے جائیں گے.لفظ اِیْلٰف کے متعلق پہلے مفسرین کی ٹھوکر عجیب بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بڑے بڑے عالم بھی
Page 403
ٹھوکر کھا جاتے ہیں.باوجود اس کے کہ یہاں صریح طور پر اِیْلٰــــفٌ کا لفظ استعمال ہوا ہے بعض مفسر اس کے معنے اِلَافٌ کے کر جاتے ہیں یعنی بجائے محبت پیدا کرنے کے وہ صرف محبت کرنے کے معنے لیتے ہیں.حالانکہ محبت کرنے کے تو یہ معنے ہوتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں یا میرے دل میں محبت ہے.لیکن محبت پیدا کرنے کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ میں دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرتا ہوں.دراصل اس لفظ کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس سے دھوکا لگ جاتا ہے.اٰلَفَ میںدو ہمزے آتے ہیں یعنی اصل لفظ اگر لکھا جائے تو اس کی شکل یوں گی أَأْ لَفَ.لیکن عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب دو ہمزے اکٹھے ہو جائیں تو دونوں ہمزوں کو ملا کر مد بنا دیتے ہیں.یعنی بجائے أَأْ کہنے کے ہم اٰ کہہ دیں گے مثلاً أَأْمَنَ کو ہم أَأْمَنَ نہیں کہیں گے بلکہ ہمزوں کی جگہ مد استعمال کر کے اٰمَنَ کہہ دیں گے.اسی طرح أَأْلَفَ کو اٰلَفَ کہہ دیں گے.مگر عربی زبان میں اٰلَفَ کے دو وزن ہیں اور اسی وجہ سے اس کے دو الگ الگ مصدر آتے ہیں.وہ دو فَاعَلَ اور اَفْعَلَ ہیں.کبھی یہ لفظ فَاعَلَ کے وزن پر ہو گا اور کبھی اَفْعَلَ کے وزن پر.جب فَاعَلَ کے وزن پر ہو تو اس کا مصدر فِعَالٌ کے وزن پر آئے گا جب فعل اَفْعَلَ کے وزن پر ہو گا تو مصدر اِفْعَالٌ کے وزن پر ہو گا بات یہ ہے کہ عربی زبان میں تمام افعال کا وزن بیان کرنے کے لئے ف.ع.ل.کے حروف کو استعمال کیا جاتاہے اور ہر لفظ کا وزن انہی تین حرفوں کے ہیر پھیر سے نکالا جاتاہے.اگر فَاعَلَ کے وزن پر کوئی لفظ بنانا ہو گا تو چونکہ فَاعَلَ میں ف کے بعد ایک الف زائد ہے اس لئے اس میں بھی ہم پہلے حرف کے بعد ایک الف زائد کر دیں گے.اور اگر اَفْعَلَ کے وزن پر کوئی لفظ بنانا ہو گا تو چونکہ اَفْعَلَ الف پہلے حرف یعنی ف سے پہلے ہے ہم اس لفظ کے پہلے حرف کے پہلے ایک الف بڑھا دیں گے.اس قاعدہ سے ظاہر ہے کہ اَلَفَ کے لفظ سے اگر ہم فَاعَلَ کے وزن پر لفظ بنانا چاہیں گے تو اسے اٰلَفَ لکھیں گے اور اگر اَفْعَلَ کے وزن پر لفظ بنانا چاہیں تو بھی اسے اٰلَفَ لکھیں گے لیکن فرق یہ ہو گا کہ جب فَاعَلَ کے وزن پر ہم اٰلَفَ کا لفظ بنائیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اٰ کے دو ہمزوں میں سے پہلا ہمزہ اَلَفَ کا ہے اور دوسرا ہمزہ فَاعَلَ کے وزن کا ہے.اور جب اَفْعَلَ کے وزن پر یہ لفظ بنائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ پہلا ہمزہ تو اَفْعَلَ کے وزن کا ہے اور دوسرا ہمزہ اصل لفظ کا ہے.ورنہ ظاہری شکل ایک ہوگی.لیکن جب ان لفظوں سے مصدر بنائیں گے تو وہ مصدر مختلف شکلوں کے ہوں گے اٰلَفَ بوزن فَاعَلَ سے بنا ہوا مصدر اِلَافٌ ہو گا اور اٰلَفَ بوزن اَفْعَلَ سے بنا ہوا مصدر اِیْلَافٌ ہوگا کیونکہ فَاعَلَ کا مصدر فِعَالٌ کے وزن پر آتا ہے اور اَفْعَلَ کا مصدر اِفْعَالٌ کے وزن پر آتا ہے.پس جبکہ اٰلَفَ سے بنے ہوئے دونوں لفظ جو فَاعَلَ اور اَفْعَلَ کے وزن پر ہوں شکل میں ایک ہوں گے اور ان کے معنوں کا فرق صرف سیاق و سباق سے معلوم ہوگا.مصدر کی
Page 404
صورت میں معنوں کا فوراً پتہ لگ جائے گا کیونکہ دونوں کے مصدر الگ الگ شکل کے ہیں اسی لئے یہاں مصدر استعمال کیا گیا ہے تاکہ معنے واضح ہو جائیں.لیکن تعجب ہے کہ بعض بڑے علماء نے باوجود اِیْلَاف کا مصدر استعمال ہونے کے اس جگہ اٰلَفَ کے معنے کئے ہیں جس کا مصدر اِلَافٌ ہے اور بعض نے تو قرأۃ دو میں سے ایک جگہ اِلَافٌ کا لفظ پڑھنا جائز سمجھا ہے.جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں وہ اٰلَفَ جس کا مصدر اِیْلٰفٌ ہو اس کے معنے کسی دوسرے کے دل میں محبت پیدا کر دینے کے ہوتے ہیں خصوصاً مکان یا مقام کی محبت.چنانچہ کہتے ہیں اٰلَفْتُہٗ مَکَانًا کَذَا جَعَلْتُہٗ یَاْلِفُہٗ (اقرب) میں نے فلاں مکان کے متعلق اس سے اِیْلَاف کیا یعنی اس کے دل میں اس مکان کی محبت پیدا کر دی.اسی طرح اٰلَفَہٗ اِیْلَافًا کے ایک معنے یہ بھی ہیں کہ ہَیَّأَہٗ وَ جَھَّزَہٗ.اس کو سامان دیا اور اسے تیار کر دیا.پھر ایک محاورہ اٰلَفَہٗ اِیَّاہُ بھی عربی زبان میں استعمال ہوتاہے جس کے معنے ہوتے ہیں اَلْزَمَہٗ اِیَّاہُ اس کے ساتھ اسے لازم کر دیا یا اس کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کر دیا.پہلے معنوں کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ کے یہ معنے ہوں گے کہ قریش کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لئے یا انس پیدا کرنے کے لئے ہم نے اصحابِ فیل کو تباہ کیا.گویا یہاں اضافت مفعولی ہے.آگے رہا یہ سوال کہ اس کا دوسرا مفعول کیا ہے.تو اس کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ مفسرین نے دوسرا مفعول رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ کا جملہ قرار دیا ہے یعنی سردی گرمی کے سفروں کی محبت پیدا کرنے کے لئے یا سردی گرمی کے سفروں کو محبوب بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصحابِ فیل کو تباہ کیا.دوسرے معنے اٰلَفَ اِیْلَافًا کے تیار کرنے اور سامان مہیا کرنے کے ہوتے ہیں.سامان مہیا کرنے کے معنوں کے رو سے اس آیت کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ قریش کو گرمی سردی کے سفر پر تیار کرنے کے فعلِ الٰہی پر تعجب کرو یعنی اس قوم کا سفروں پر آمادہ ہو جانا یا ان سفروں کے لئے ہر قسم کے سامانوں کا اس کے لئے مہیا ہو جانا ایک ایسی چیز ہے جو قابل تعجب ہے.درحقیقت تیار کرنے کے معنے سامان مہیا کرنے کے بھی ہوتے ہیں.پس اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے امن قائم کر دیا.رستے کھول دیئے.لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی.ان کا احترام پیدا کر دیا اور پھر خود ان کے دلوں میں اس خواہش کا پیدا ہو جانا بھی ایک تعجب کی بات ہے کیونکہ وہ مکہ کے عاشق تھے اور سفر پر جانا پسند نہیں کرتے تھے.تیسرے معنے اِیْلَاف کے کسی چیز کو لازم کر دینے کے ہیں.ان معنوں کےر و سے اس آیت کا یہ مطلب ہے
Page 405
کہ ہم نے اصحابِ فیل کو تباہ کیا تاکہ ہم قریش کو شتاء و صیف کے سفروں سے وابستہ کر دیں وہ ان کو چھوڑیں نہیں.اگر ہم اصحاب فیل کو تباہ نہ کرتے تو یہ اس امر پر مجبور ہو جاتے کہ سفروں کو چھوڑ دیں لیکن ہمارا منشا یہ تھا کہ سفروںپر قائم رہیں اور چونکہ ہمارا منشا یہ تھا کہ یہ سفروں پر قائم رہیں اس لئے ہم نے اصحاب فیل کو تباہ کر کے ایسے سامان کر دیئے کہ انہیں سفر چھوڑنے کے لئے کوئی مجبوری پیش نہ آئی.چوتھے معنے یہ ہیں کہ قریش کو سردی گرمی کا سفر کرنے کی محبت پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یعنی فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ کا صلہ بنا کر اس کے یہ معنے ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر ایک بہت بڑا انعام کیا ہے اور وہ یہ کہ ان کے دلوں میں اس نے سردی گرمی اور شتاء و صیف کے سفر کی محبت پیدا کر دی ہے پس یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے کہ اس نے شتاء و صیف کے سفر کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہے اور پھر اس کے لئے اس نے سامان بھی مہیا کر دیئے ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی عبادت کریں.پانچویں معنے یہ ہیں کہ قریش کے اپنے نفسوں پر سردی گرمی کا سفر واجب کر دینے پر تعجب کر.یعنی یہ کیوں گھروں میں بیٹھ کر عبادت نہیں کرتے اور سفر کرتے ہیں.اس کے متعلق بھی آگے جہاں مضمون کی تفصیل آئے گی میں روشنی ڈالوں گا اس جگہ میں صرف یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ان معنوں پر اس کی موجودہ شکل میں اعتراض ہے.اس جگہ پر بعض مفسرین نے ایک نکتہ بیان کیا ہے اور وہ نکتہ اِیْلَاف کے متعلق ہے.وہ کہتے ہیں کہ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اٖلٰفِهِمْ میں دو اِیْلَاف آتے ہیں.ایک اِیْلَاف لفظ قریش سے پہلے آتا ہے اور ایک اِیْلَاف لفظ قریش کے بعد آتا ہے.وہ کہتے ہیں پہلے اِیْلَاف کے بارہ میں قُرّاء میں اختلاف پایا جاتا ہے.کہ اسے اِلَاف پڑھنا چاہیے یا اِیْلَاف.بعض کہتے ہیں کہ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اٖلٰفِهِمْ نہیں بلکہ لِاِلَافِ قُرَيْشٍ اٖلٰفِهِمْ پڑھنا چاہیے اور بعض اِلَافِ قُرَیْش نہیں بلکہ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید کی تحریر میں سب متفق ہیں کہ اس کو اِیْلٰف ہی لکھنا چاہیے اِلَاف نہیں لکھنا چاہیے.گویا پڑھتے تو بعض اس کو اِلَاف ہیں لیکن لکھتے وقت وہ اسے اِلَاف نہیں بلکہ اِیْلَاف لکھتے ہیں.اس کے مقابلہ میں اٖلَافِھِمْ کے متعلق لکھنے میں تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ اسے اِیْلَاف لکھا جائے گا لیکن پڑھنے میں سب اسے اِلَافِھِمْپڑھیں گے.انہوں نے اس سے ایک استدلال کیا ہے جو نہایت ہی لطیف استدلال ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی حفاظت کا یہ ایک زبردست ثبوت ہے کہ قرآن کریم کی تحریر بھی اور روایت بھی ایسی پختگی
Page 406
کے ساتھ قائم ہیں کہ ان کے بارہ میں کسی کو شبہ کی گنجائش ہی نہیں.اگر یہ تحریر کسی شبہ کا موجب ہو سکتی تھی اور اگر کوئی شخص بھی خیال کرتا کہ اس تحریر میں غلطی رہ گئی ہے تو جو لوگ اس عقیدہ کے قائل تھے کہ پہلا اِیْلَاف دراصل اِلَاف ہے وہ جس طرح اس کو اِلَاف پڑھتے ہیں اسی طرح تحریر میں بھی اس کو اِلَاف کر دیتے مگر وہ پڑھتے تو اِلَاف ہیں لیکن لکھتے اِیْلَاف ہیں.جس کے معنے یہ ہیں کہ وہ بھی اس امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسخہ پہنچا ہے اس میں اِیْلٰف ہی لکھا ہوا ہے ورنہ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ان کا خیال تو یہ ہے کہ یہ لفظ اِیْلٰف نہیں بلکہ اِلَاف ہے لیکن لکھتے اِیْلٰف ہیں اور پڑھتے اِلَاف ہیں.ان کا اِلَاف پڑھنا اور اِیْلَاف لکھنا ثبوت ہے اس بات کا کہ باوجود اس کے کہ ان کے اپنے دل میں یہ یقین تھا کہ یہاں قرأت اِلَاف ہے چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسخۂ قرآن پہنچا اس میں اِیْلَاف ہی لکھا ہوا تھا اس لئے ان میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اسے بدل سکیں.اس سے بڑا ثبوت قرآن کریم کی حفاظت کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کا اپنا خیال یہ ہے کہ اِلَاف ہے اِیْلَاف نہیں وہ بھی پڑھتے تو اِلَاف ہیں لیکن لکھتے اِیْلَاف ہیں اور وہ یہ جرأت نہیں کر سکتے کہ اس کو بدل دیں.دوسرا اِیْلٰف جو ہے یہ قرآن کریم کے ان نسخوں میں جو ہمارے ملک میں چھپتے ہیں یا کی بجائے کھڑی زیر کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے مگر اس سے یہ لفظ اِلَاف نہیں بن جاتا بلکہ اِیْلٰف ہی رہتا ہے.دراصل لکھنے کے دونوں طریق مروّج ہیں یا کے ساتھ بھی اس لفظ کو لکھ لیتے ہیں اور کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھ لیتے ہیں.مگر مفسرین کے نزدیک قُرّاء اسے پڑھتے تو اِیْلٰف ہیں مگر لکھتے اِلَاف ہیں.انہیں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ وہ تحریر میں تبدیلی کر کے اسے یا کے ساتھ لکھنا شروع کردیں.ورنہ جب ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں یاء ہے تو وہ تحریر میں بھی اس کو یا کے ساتھ بدل سکتے تھے لیکن قرأت کے اختلاف کے باوجود وہ لکھتے تو اٖلَاف ہیں مگر پڑھتے اِیْلٰف ہیں.یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہر شخص خواہ وہ موافق تھا یا مخالف یہ یقین رکھتا تھا کہ اسے قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح پہنچا ہے اس میں تبدیلی کرنے کی اسے جرأت نہیں ہوتی تھی.یہ قرآن کریم کے محفوظ اور غیرمحرف ہونے کی ایک نہایت ہی عمدہ اور لطیف دلیل ہے.اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ.اٖلٰفِهِمْ کو دوبارہ زور دینے کے لئے دہرایا گیا ہے اور یہ پہلے اِیْلٰف کا بدل ہے.بدل سے مراد یہ ہے کہ وہی لفظ اپنی اصلی شکل میں یا اپنے کسی ہم معنیٰ لفظ کی شکل میں کلام پر زور دینے کے لئے دوبارہ لایا جاتا ہے.ہمارے ہاں اردو میں بھی اس قسم کے فقرات استعمال ہوتے ہیں.میں نہیں جانتا کہ اردو میں اسے بدل کہتے ہیں یا کچھ اور.بہرحال جب کلام پر زور دینا مطلوب ہوتو اردو میں بھی بات کو دہرایا جاتا ہے مثلاً کہا
Page 407
جاتا ہے.دیکھو میاں میں تمہیں کہتا ہوں.دیکھو میاں میں تمہیں کہتا ہوں.گو یا لفظاً یا معناً بعض دفعہ ایک بات کو زور دینے کے لئےدہرایا جاتا ہے پس اٖلٰفِهِمْ پہلے اِیْلٰف کا بدل ہے اور معنے یہ ہیں کہ ہم نے قریش کے اِیْلٰف کےلئے ایساکیا ہاں ہاں ہم نے قریش کے اِیْلٰف کے لئے ایسا کیا اردو میں ایسے موقعہ پر بعض دفعہ ہاں ہاں کا لفظ بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں یقینی اور قطعی بات ہے.یہ زور جو یہاں کلام پر دیا گیا ہے اس کے متعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زور رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ پر ہو یعنی ہم نے قریش کے دل میں اِیْلٰف پیدا کیا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اِیْلٰف پیدا کیا رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ کے متعلق.گویا یہ زور رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ پر ہو لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اِیْلٰف پر زور دیا گیا ہو اور خود اسی مضمون کے لئے یہ لفظ دوبارہ لایا گیا ہو یعنی ہم نے اِیْلٰف کے لئے رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ کا انتظام کیا.اس جگہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کا معنوں کا اختلاف مضمون کو مبہم نہیں کر دیتا.ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اس آیت کے تو پانچ چھ معنے ہوگئے ہیں اور مضمون مبہم ہو گیا ہے.مگر یہ غلط ہے اس قسم کا اختلاف مضمون کو مبہم نہیں کرتا بلکہ کلام الٰہی میں ایسا اختلاف مضامین کو وسیع کر دیتاہے اور وہ سب معنے ہی ایک وقت میں مدنظر ہوتے ہیں کیونکہ ہم قرآن کریم کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدائے علیم و خبیر کا کلام ہے.اگر ایک لفظ کے استعمال سے تین یا چار معنے نکل سکتے تھے اور ان میں سے دو یا تین معنے الٰہی منشاء میں نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ معنے لئے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی وضاحت میں کون سی مشکل تھی وہ باقی معنوں کی نفی کر دیتا اور بتا دیتا کہ یہاں صرف فلاں معنے مراد ہیں.آخر جب خدا نے ایک ایسا جملہ یا لفظ استعمال کیا تھا جس کے کئی معنے ہو سکتے تھے اور خدا تعالیٰ کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ علیم و خبیر ہے وہ جانتا تھا کہ اس کے ایک ایک لفظ سے کیا کیا معنے نکلیں گے تو وہ ان معنوں کی تردید کر دیتا اور کہتا کہ میرا مطلب صرف فلاں معنے سے ہے باقی معنے یہاں مراد نہ لئے جائیں.اگر انسان کا کلام ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ انسان غلطی کر سکتا ہے وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کے معنے کیا ہیں یا بعض دفعہ معنے تو جانتا ہے مگر اس لفظ کے استعمال کرتے وقت وہ معنے اس کے ذہن میں نہیں ہوتے اور اس طرح غلطی کر جاتا ہے ہمارے ملک کا مشہور لطیفہ ہے کہ نواب سعادت علی خاں کی مجلس میں ایک دفعہ سید انشاء اللہ خاں بیٹھے ہوئے تھے.نواب سعادت علی خاں لونڈی زادہ تھے اور اکثر لوگ اس کا علم رکھتے تھے.ایک دن وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے ان کی تعریفیں شروع کر دیں.قاعدہ یہ ہے کہ بادشاہ پر جس قسم کا اعتراض ہو سکتا ہو.عموماً لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں تاکہ اس کا دل خوش ہو اور وہ سمجھے کہ یہ لوگ
Page 408
میرے وفادار ہیں.جب بادشاہ کی تعریفیں شروع ہوئیں تو بعضوں نے کہا کہ حضور کا کیا ہے حضور تو نجیب الطرفین ہیں ہم تو حضور کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے.اس طرح وہ تعریفیں کر کے لونڈی زادہ ہونے کا الزام دور کر رہے تھے کہ انشاء اللہ خاں بھی بول اٹھے ان کی عادت تھی کہ جو بھی کوئی بات کر رہا ہوتا اس سے بڑھ کر بات کرتے.چونکہ بادشاہ کے بہت منہ چڑھے ہوئے تھے اس لئے وہ ہمیشہ دربار میں دوسروں سے بڑھ کر بات کرنے کے عادی تھے تاکہ بادشاہ یہ سمجھے کہ یہی میرے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں.جب لوگوں نے تعریف کی اور کہا کہ حضور تو نجیب الطرفین ہیں تو انشاء اللہ خاں کو بھی جوش آیا اورانہوں نے کہا نجیب الطرفین کیا حضور تو اَنْـجَبْ ہیں.عربی زبان میں جب اَفْعَل کے وزن پر لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنے ہوتے ہیں دوسروں سے زیادہ اس میں یہ خوبی ہے مثلاً جب اَمْـجَد کہا جائے تو اس کے معنے ہوں گے زیادہ مجد والا.جب اَکْرَم کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کے معنے ہوں گے زیادہ کرم والا.چونکہ درباری بادشاہ کو نجیب الطرفین قرار دے رہے تھے انہوں نے کہا نجیب الطرفین کیا حضور تو اَنْـجَب ہیں یعنی سب سے زیادہ شریف ہیں.مگر بدقسمتی سے عربی زبان میں اَنْـجَب کے معنے لونڈی زادہ کے بھی ہیں.وہ کہہ تو بیٹھے مگر اس وقت ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اس لفظ کے اور معنے بھی پائے جاتے ہیں اور وہ معنے ایسے ہیں جن سے بادشاہ پر زد پڑتی ہے.پھر بعض دفعہ ایک بات تو منہ سے نکلتی ہے مگر اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا مگر خدا کی قدرت ہے اس وقت کئی علماء بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اورخود بادشاہ بھی عربی جانتا تھا.انہوں نے اَنْـجَب کہا تو یک دم تمام درباریوں اور بادشاہ کا ذہن اَنْـجَب کے انہی معنوں کی طرف چلا گیا اور تمام دربار پر سناٹا چھا گیا.اس کے بعد انہوں نے اور کئی قسم کی باتیں کر کے اس اثر کو زائل کرنا چاہا مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کو ان سے اتنی عداوت ہو گئی کہ اس نے انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیا.چنانچہ یا تو وہ بادشاہ کے اتنے منہ چڑھے تھے کہ ہر وقت دربار میں رہتے اور یا گرتے گرتے بہت ہی ادنیٰ حالت کو پہنچ گئے.تو انسان غلطی کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسا لفظ استعمال کرے جس کے معنے وہ نہ جانتا ہو.مگر کیا خدا تعالیٰ بھی ایسا کر سکتا ہے.کیا خدا تعالیٰ کو یہ معلوم نہیں کہ میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں ان سے کیا کیا معنے نکل سکتے ہیں.جب خدا علیم و خبیر ہے اور وہ جانتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنے بھی ہو سکتے ہیں، تین معنے بھی ہو سکتے ہیں، چار معنے بھی ہو سکتے ہیں.تو اگر خدا تعالیٰ ان سب میں سے کوئی ایک معنے لینا چاہتا تھا تو خدا تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت کے شایاں یہ امر تھا کہ وہ کوئی ایسا اشارہ کر دیتا جس سے پتہ لگ جاتا کہ یہاں صرف دوسرے معنے مراد ہیں.تیسرے معنے مراد نہیں یا چوتھے اور پانچویں معنے مراد نہیں.لیکن اگر کلام ایسا ہو کہ اس کے زیادہ معنے ہو سکتے ہوں اور
Page 409
خدا تعالیٰ نے ان معنوں کو ردّ نہ کیا ہو تو تفسیر کا یہ اصول ہے کہ پھر وہ سارے معنے مراد لئے جائیں گے.اس لئے کہ اس کلام کا کہنے والا عالم الغیب خدا ہے.اگر وہ معنے اس کے مدّ ِنظر نہ ہوتے تو وہ ان کی تردید کیوں نہ کرتا.چنانچہ قرآن کریم میں جب بھی ایک ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس سے کوئی شبہ پیدا ہوتاہے وہیں اس شبہ کا ازالہ بھی کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ میری مراد ان معنوں سے یہ نہیں بلکہ یہاں اس کے اور معنے ہیں.پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ (یوسف:۱۱۲) یعنی یہ قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں کوئی جھوٹی باتیں نہیں بلکہ یہ کلام پہلی تمام پیشگوئیوں کو پور اکرنے والا ہے اور ہر قسم کے مضامین اس میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں لیکن قرآن کریم ہے کتنی کتاب؟ انجیل سے بھی چھوٹی ہے پس جب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ دعویٰ پیش کیا گیا ہے کہ اس کتاب میں وہ ہر قسم کے مضامین بیان کر دیئے گئے ہیں جو دینیات سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ اتنی چھوٹی سی کتاب میں وہ تمام مضامین تفصیل کے ساتھ نہیں آسکتے تھے.پھر تو قرآن کریم کی ہزاورں ہزار جلدیں چاہیے تھیں.اور اگر ہزاروں ہزار جلدیں ہوتیں تو لوگ اس کو حفظ نہ کر سکتے اور اس طرح قرآن کریم کی حفاظت مشتبہ ہو جاتی.اب اگر لوگ قرآن کریم کو آسانی سے حفظ کر لیتے ہیں تو اس لئے کہ قرآن کریم حجم کے لحاظ سے ایک چھوٹی سی کتاب ہے.اگر اغانی کی طرح بیس۲۰ جلدوں میں قرآن کریم ہوتا یا لسان العرب کی طرح اس کی بیس۲۰ جلدیں ہوتیں تو کتنے لوگ اس کو حفظ کرنے والے ہوتے؟ یہ لازمی بات تھی کہ بہت تھوڑی تعداد میں ایسے لوگ نکلتے جو اتنی بڑی کتاب کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے.پھر اس کی لمبائی خود اس کتاب کو مشتبہ کر دیتی اور لوگ کہتے کہ چونکہ اتنی بڑی کتاب حافظ حفظ نہیں کر سکتے اس لئے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی.مگر اب ہزاروں ہزار نہیں لاکھوں حافظ دنیا میں موجود ہیں اور بڑے بڑے شدید دشمن یہاں تک کہ میور، نولڈکے اور سپرنگر جیسے شخص بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کے متعلق خواہ کچھ بھی کہیں اس امر سے انکار نہیں کر سکتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صورت میں یہ کتاب اپنے صحابہؓ کو دی تھی اسی صورت میں وہ آج بھی محفوظ ہے.وہ اس امر کے تو قائل نہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی ہے مگر وہ یہ تسلیم کئے بغیر نہیں رہتے کہ جس صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنے متبعین کو دی تھی اسی صورت میں یہ کتاب آج بھی موجود ہےاور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی.چنانچہ بعض نے کھلے طو رپر کہا ہے کہ ہم انجیل یا بائبل کی طرح اس پر اعتراض نہیں کر سکتے.اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کتابوں کو کوئی حفظ نہیں کرتا مگر قرآن کریم کو حفظ کرنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں مگر یہ بھی لازمی بات ہے
Page 410
کہ یہ کتاب اسی صورت میں حفظ ہو سکتی تھی جب مختصر الفاظ میں ہوتی.غرض ایک طرف اس کو یاد کرنے کی اہمیت مجبور کرتی تھی کہ یہ کتاب مختصر ہو مگر دوسری طرف قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ وہ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ ہے تقاضا کرتا تھا کہ سارے مضامین اس میں آجائیں.قرآن کریم کی ایک آیت کے متعدد معنی ہونے کی دلیل اب یہ دونوں باتیں کس طرح اکٹھی ہوسکتی تھیں؟ یہ اسی طرح اکٹھی ہو سکتی تھیں کہ ایک ایک جملہ میں کئی کئی مضامین ہوں.اگر ہم اس حکمت کا انکار کر دیں تو قرآن کریم میں تمام مضامین کس طرح آسکتے ہیں.پس قرآن کریم کے یہ دو دعوے یعنی ایک یہ کہ اس کی حفاظت کی جائے گی زبانی بھی اور تحریری بھی.اور دوسرا یہ کہ تمام مضامین اس میں آگئے ہیں لازماً اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے کئی کئی معانی ہیں.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایک آیت کے سات بطن ہیں(بخاری کتاب فضائل القراٰن باب انزل القرآن علٰی سبعۃ احرف).اگر ایک ایک بطن کے سات معنے بھی ہوں تو ایک ایک آیت کے ۴۹ معنے تو یہی ہو گئے.پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح کر کے بتا دیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت بڑے وسیع مطالب پر حاوی ہے.بہرحال جب قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ اس میں تمام مضامین ہیں اور جب قرآن کریم نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو حفظ کیا جائے گا اور اس طرح اس کی ظاہری حفاظت کی جائے گی تو ان دونوں باتوں کو ملا کر خود بخود یہ نتیجہ نکل آیا کہ قرآن کریم ایسی عبارت میں نازل کیا جائے گا جو مختصر بھی ہو اور وسیع مطالب پر بھی مشتمل ہو.اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے طریقِ کلام کو اختیار کرتا.ورنہ اس کتاب کی وسعت ہزاروں جلدوں میں بھی نہ آسکتی.پس قرآن کریم ایسی عبارت میں نازل کیا گیا ہے کہ ایک ایک جملہ اور فقرہ کے کئی کئی معنے نکلتے ہیں اور اگر کوئی معنے مراد نہیں ہوتے تو اسی جگہ یا دوسری جگہ ان معنوں کی تردید کر دی جاتی ہے.اس طرح مختصر لفظوں میں بے انتہا مطالب آگئے ہیں.اور آیاتِ زیر تفسیر میں بھی اسی کمال کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مختلف مضامین ایک خاص اسلوبِ بیان سے پیدا کئے گئے ہیں اور سب ہی درست ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر فائدہ دیتے ہیں اورتبلیغ حقہ میں مفید ہیں.پس کئی معنوں سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابہام ہو گیا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کمال ہو گیا.فقرہ چھوٹا سا ہے اور اس کے معنے بہت وسیع ہیں.مثلاً قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی آیت آتی ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا(الدھر :۹) اس آیت میں صرف ایک ضمیر کے ذریعہ سے مضمون کو اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ اس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے.یہ ایک فلسفیانہ مضمون ہے جو ان آیات میں بیان ہو اہے.اور اگر اس فلسفہ پر بحث کی
Page 411
جائے تو یقیناً اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہی ہم ایک کتاب لکھ سکتے ہیں.چنانچہ اس آیت میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے اس کے ایک ایک حصہ پر یورپ کے بعض فلاسفروں نے مستقل طور پر بعض کتابیں لکھی ہوئی ہیں.مثلاً اس آیت سے پہلے خدا تعالیٰ کا ذکر آتا ہے اس لئے اس آیت کے یہ معنے بنیں گے کہ ’’وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے.‘‘ پھر قریب ہی طعام کا لفظ ہے اس لئے ضمیر اس کی طرف بھی جا سکتی ہے.اس لحاظ سے اس کے یہ معنے ہوں گے کہ ’’وہ کھانا کھلاتے ہیں باوجود کھانے کی محبت کے‘‘ یعنی خود بھوکے ہوتے ہیں انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے مگر بھوکے رہ کر اور تکلیف اٹھا کر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں.تیسرے معنے اس کے یہ بنتے ہیں کہ ’’وہ کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلانے کی محبت کی وجہ سے.‘‘ اور وہ اس کام کو خود اس کام کے شوق کی وجہ سے کرتے ہیں.یہ تین اعلیٰ درجہ کے اخلاقی مدارج ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں اور جس پر موجودہ زمانہ میں یوروپین فلاسفروں نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں.انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ نیکی کیا ہے اور ہمیں کیوں کرنی چاہیے اس کا جواب بعض فلسفیوں نے یہ دیا ہے کہ نیکی وہ ہے جو محض نیکی کے لئے کی جائے.اس کے کرتے وقت کوئی خاص غرض مدّ ِنظر نہ ہو (Encyclopedia of Religion and Ethics Under word "Virtue").بعض اور فلسفیوں نے کہا ہے کہ نیکی وہ ہے جو کسی Great Ideal یعنی اعلیٰ درجہ کے مقصد کو مدّ ِنظر رکھ کر کی جائے اور بعضوں نے کہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی خاطر کام کیا جائے.(The New International Webster,s Coprehensive Dictionary of the English Language Under word "Virtue") یہ تینوں فلسفیانہ نکتے يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ میںبیان کئے گئے ہیں.اس معیار کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ نیکی ایسے وقت میں کرنی چاہیے کہ خود تکلیف میں ہو لیکن دوسروں کے لئے ایثار کرے.اسی طرح اس معیار کو بھی تسلیم کیاگیا ہے کہ نیکی محض نیکی کی خاطر کی جائے.چنانچہ فرماتا ہے کہ ہمارے مومن بندے محض ایک نیک کام کو اس کی ذاتی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں اور پھر اس معیار کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ نیک کام وہ ہے جو ایک ہائر آئیڈیل کے لئے کیا جائے.چنانچہ فرماتا ہے يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ وہ دوسروں کو محض خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں.ان کے مدّ ِنظر کوئی دنیوی غرض نہیں ہوتی بلکہ ایک بلند و بالا مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے جو یہ ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے.ان تین اخلاقی نکتوں پر موجودہ زمانہ کے فلسفیوں نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں اور کسی نے کسی کو اعلیٰ قرار دیا ہے اور کسی نے کسی کو.مگر قرآن کریم نے صرف ایک مختصر سی ضمیر رکھ کر ایسی تعلیم پیش کر دی ہے جو ان تمام فلسفوں پر حاوی ہے.اگر کوئی فلاسفر ہمارے پاس
Page 412
آئے اور کہے کہ میں اس بات کو اچھا سمجھاتا ہوں کہ نیکی محض نیکی کی خاطر کی جائے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے قرآن کریم میں یہ تعلیم موجود ہے چنانچہ ہم یہ آیت نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے.اگر دوسرا فلاسفر یہ کہے کہ میں تو اس بات کو نیکی سمجھتا ہوں کہ دوسروں کی خاطر تکلیف اٹھا کر کام کیا جائے.تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے قرآن کریم میں یہ تعلیم موجود ہے چنانچہ ہم یہی آیت نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے.پھر کوئی تیسرافلسفی ہمارے پاس آجائے اورکہے کہ نیکی وہ ہے جو کسی ہائر آئیڈیل کے لئے کی جائے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے قرآن کریم کی یہی تعلیم ہے چنانچہ ہم یہی آیت نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے.اگر ہٖ کی جگہ طعام کا لفظ ہوتا یا اللہ کا لفظ ہوتا یا اِطْعَام کا لفظ ہوتا تو گو ایک معنے تو آجاتے مگر باقی دو معنے باطل ہوجاتے.یہی حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ضمیر استعمال کی ہے کوئی اسم استعمال نہیں کیا.ورنہ وہ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّ اللّٰہِ بھی کہہ سکتا تھا وہ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّ الطَّعَامِ بھی کہہ سکتا تھا.وہ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّ الْاِطْعَامِ بھی کہہ سکتا تھا مگر اس نے یہ نہیں کہا بلکہ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ کہا تاکہ ہٖ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف بھی چلی جائے، طعام کی طرف بھی چلی جائے اور اطعام کی طرف بھی چلی جائے.پس قرآن کریم کا یہ ایک بہت بڑا کمال ہےکہ وہ مختصر الفاظ میں اتنا مضمون بھر دیتا ہے کہ اور لوگ بڑی بڑی کتابوں میں بھی اس کو بیان نہیں کر سکتے.پس مختصر پُر از معانی کلام پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا.ہاں جہاں بعض معنے اللہ تعالیٰ کے منشاء کے خلاف ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا مقصد کسی خاص معنوں کی طرف انسانی ذہن کو لے جانا ہوتا ہے تو وہاں فوراً اشارہ ہو جاتا ہے کہ صرف فلاں معنے لئے جائیں اور معنے نہ لئے جائیں بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم میں بعض جگہ ایک ایسا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے دو معنے ہو سکتے ہیں تو ساتھ ہی قرآن کریم کی طرف سے اس کے معنے بھی دیئے ہوئے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہاں یہ لفظ صرف ان معنوں میں استعمال ہوا ہے دوسرے معنے مرا دنہیں لئے گئے.اب پیشتر اس کے کہ میں ان آیات کی تفسیر کروں میں لفظ قریش کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں.قُرَيْشٍ.قُرَیْش کا لفظ قَرَشَ سے نکلا ہے جس کا مضارع دونوں طرح آتا ہے قَرَشَ یَقْرُشُ اور قَرَشَ یَقْرِشُ.قَرْشًا ان کا مصدر ہے.اور قَرَشَ کے معنے ہوتے ہیں قَطَعَہٗ اس کو کاٹ دیا.اور قَرَشَ الشَّیْءَ کے معنے ہوتے ہیں جَـمَعَہٗ مِنْ ہُنَا وَمِنْ ھُنَا وَ ضَـمَّ بَعْضَہٗ اِلٰی بَعْضٍ.چیز کو کچھ یہاں سےاور کچھ وہاں سے لیا اور اکٹھا کر کے رکھ دیا.اور قَرَشَ مِنَ الطَّعَامِ کے معنے ہوتے ہیں اَصَابَ مِنْہُ قَلِیْلًا تھوڑا سا کھانا کھا لیا.اور قَرَشَ الْـجَیْشَ بِالرِّمَاحِ کے معنے ہوتے ہیں طَعَنُوْا بِـھَا.لشکر نے نیزوں کے ساتھ اپنے دشمن کو مارا اور قَرَشَ
Page 413
فُلَانٌ لِعِیَالِہٖ کے معنے ہوتےہیں کَسَبَ.اس نے اپنے لئے یا اپنے خاندان کے لئے کمائی کی.اسی سے ایک اور لفظ قِرْش نکلا ہے جس کے متعلق لکھا ہے دَابَّۃٌ تَکُوْنُ فِی الْبَحْرِ.قرش سمندر میں رہنے والا ایک جانور ہے لَا تَدَعُ دَابَّۃً اِلَّا اَکَلَتْـھَا وہ سب جانوروں کو کھا جاتا ہے فَـجَمِیْعُ الدَّوَابِّ تَـخَافُھَا.اس وجہ سے سارے سمندری جانور اس سے ڈرتے ہیں وَقَبِیْلَۃٌ مِّنَ الْعَرَبِ اور اس کے معنے عرب کے ایک قبیلہ کے بھی ہیں.وَاِنْ اَرَدْتَّ بِقُریْشٍ اَلْـحَیَّ صَـرَّفْتَہٗ اور اگر قریش کے معنے تم حَیٌّ کے لو (حی کے معنے بھی قبیلہ کے ہوتے ہیں) تو پھر یہ لفظ منصرف ہو گا جیسے اسی سورۃ میں آتا ہے لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اس میں ش کے نیچے تنوین آئی ہے یعنی اس جگہ یہ لفظ منصرف استعمال ہوا ہے وَاِنْ اَرَدْتَّ الْقَبِیْلَۃَ لَمْ تَصْـرِفْہُ لیکن اگر قبیلہ کا لفظ مراد لو تو پھر یہ غیرمنصرف ہو گا.یعنی قریش کے آخر میں تنوین نہ آسکے گی اور نہ اس کے نیچے زیر آسکے گی.اس قبیلہ کے آدمیوں کو قُرَشِیٌّ بھی کہتے ہیں اور قُرَیْشِیٌّ بھی کہتے ہیں(اقرب).سیبویہ جو نحو کے بہت بڑے ماہر اور امام سمجھے جاتے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ حی سمجھ کر منصرف بنانا اصل قاعدہ ہے.لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسے قبیلہ قرار دے کر غیر منصرف بنانا بھی جائز ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا گویا چاہیں تو قُرَیْشَ پڑھ لیں اور اسے منصرف نہ بنائیں اس صورت میں علم اور تانیث دو وجہیں پیدا ہو جائیں گی جن کی وجہ سے یہ غیرمنصرف ہو جائے گا.قِرْش کے متعلق مفسرین اپنے زمانہ کے ملاحوں کی روایتوں کی بناء پر لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سمندری جانور ہے جو کشتیوں پر حملہ کرتا اور انہیں مار کر الٹا دیتا ہے اورسوائے آگ اور روشنی کے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتا.جب یہ جانور حملہ کرے تو لوگ آگ جلا کر اس کے منہ کے آگے رکھ دیتے ہیں.میں سمجھتا ہوں اس بیان سے جو لغت میں آیا ہے وھیل مچھلی مراد ہے.وھیل مچھلی ہی ایک ایسی چیز ہے جو زور سے اپنی دم مار کر جہازوں کو توڑ دیتی ہے.یہ مچھلی افریقہ کے ساحل پر بہت ہوتی ہے اور کراچی کے قریب بھی کبھی کبھی آجاتی ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ یہ بحیرۂ احمر کے آگے سے گذرتی ہے اور عرب کا علاقہ بحیرۂ احمر کا ہی ہے.یہ روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ وھیل مچھلی عرب کے سمندر کے کناروں پر بھی کبھی کبھی دیکھی جاتی ہے.چونکہ کراچی کے پاس بعض دفعہ وھیل مچھلی دیکھی گئی ہے.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحیرۂ احمر کے پاس سے گذر کر افریقہ کے ساحلوں سے یہ مچھلی گذرتی ہے یا پھر ہم قِرَش سے مراد شارک مچھلی بھی لے سکتے ہیں.شارک بھی چھوٹی کشتیوں پر حملہ کر کے ان کو الٹا دیتی ہے یہ تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ باقی سارے جانوروں کو کھا جاتی ہے یا نہیں مگر عرب لوگ ممکن ہے کہ جن مچھلیوں سے آشنا تھے انہیں شارک کھا جاتی ہو.
Page 414
قریش کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں اس مچھلی کی وجہ سے ہی قریش کہتے ہیں(تفسیر الخازن سـورۃ قریش).چنانچہ مفسرین نے اس بارہ میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت درج کی ہے.اسی طرح بعض اور بڑے بڑے عربوں کے اقوال بھی درج کئے ہیں چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت معاویہ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ قریش مچھلی کی وجہ سے جو سارے سمندری جانوروں سے بڑی ہوتی ہے اور ان کو کھاجاتی ہے مگر اسے کوئی نہیں کھا سکتا چونکہ قریش قبیلہ بھی عرب میں سب سے بڑا ہے اور سارے عرب قبائل اس سے ڈرتے ہیں اس لئے اسے بھی قریش کہنے لگ گئے ہیں.انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا تم اس کا ثبوت عرب شاعروں کے کلام سے دے سکتے ہو.یعنی یہ کیوں نہ سمجھ لیا جائے کہ تم نے یہ بات اپنے پاس سے بنائی ہے کہ ان کا قریش نام اس وجہ سے تھا.اگر یہ بات تم نے اپنے پاس سے نہیں بنائی تو عرب شعراء کا کوئی کلام اپنی تائید میں پیش کرو.اس پر حضرت ابن عباسؓ نے کچھ شعر پڑھے جن میں یہ ذکر آتا تھا کہ قریش کو اس لئے قریش کہتے ہیں کہ جس طرح قرش مچھلی باقی تمام سمندری جانوروں پر غالب آجاتی ہے اسی طرح قریش بھی تمام قبائلِ عرب پر غالب ہیں.مگرمیرے اپنے خیال میں یہ روایت صحیح نہیں.اس لئے کہ جو نظم بتائی جاتی ہے اس کے دیکھنے سے صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ بناوٹی ہے.کیونکہ اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ عنقریب ایک نبی ظاہر ہو گا جو تمام عرب کا مرجع اور ملجاء و ماویٰ ہو گا.اگر وہ اس قسم کے اشعار کہا کرتے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کس طرح کر سکتے تھے.انہوں نے تو بڑی بڑی مخالفتیں کیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مقابلہ کیا.پس میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت بناوٹی ہے.لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عربوں میں یہ خیال تھا اور اس کا تاریخوں سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ قریش کا قریش نام اس جانور کی وجہ سے پڑا مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں قریش کیوں کہا گیا اس جانور کا نام تو قرش ہے؟ اس کے دو جواب دیئے گئے ہیں.ایک تو یہ کہ جب اتنے بڑے جانور کا نام قرش ہے جس سے تمام سمندری جانور ڈرتے ہیں اور جو ان سب کو کھا جاتا ہے تو اس چھوٹے سے قبیلہ کا نام تو قریش یعنی چھوٹا قرش ہی موزوں تھا.گویا ان کے نزدیک قریش کو قریش اس لئے کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا قبیلہ تھا.اس لئے لوگوں نے قِرْش کہنے کی بجائے اسے قریش کہنا شروع کر دیا جس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹی سی وھیل مچھلی ہے.مگر بعضوں نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں بلکہ تصغیر کا صیغہ بعض دفعہ اظہار عظمت کے لئے بھی آتا ہے.اس لئے قریش کے معنے بڑی قرش یعنی بڑی وھیل مچھلی کے ہیں اور مراد یہ ہے کہ یہ بڑی قوم ہے.مگر یہ سارے معنے ایسے ہیں جن میں ایک حد تک تکلف پایا جاتا ہے.میں سمجھتا ہوں کہ گو یہ بات صحابہؓ
Page 415
سے بھی ثابت ہےاور عربوں سے بھی کہ قریش کو قریش اس جانور کی وجہ سے کہتے ہیں مگر صحابہؓ کے زمانہ میں یہ نام نہیں رکھا گیا بلکہ ان کے باپ دادا کے زمانہ سے یہ نام چلا آتا ہے.پھر نہ قرآن کریم نے یہ معنے بتائے ہیں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں.اگر تو وہ بتا دیتے کہ قریش کو قرش مچھلی کی وجہ سے قریش کہا جاتا ہے تو ہم کہہ دیتے کہ اٰمَنَّا و صَدَّقْنَا.اور ہم سمجھ لیتے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کو غیب کا علم حاصل ہے اور اس کے توسط سے خدا تعالیٰ کے رسول کو بھی بعض امور میں غیب کا علم حاصل ہو جاتا ہے اس لئے انہوں نے جو معنے بتائے ہیں وہی صحیح ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت مصدقہ تو الگ رہی ضعیف بھی میں نے نہیں دیکھی جس میں قریش کی وجہ تسمیہ یہ بتائی گئی ہو.باقی رہے صحابہؓ سو جو بات انہوں نے قوم سے سنی وہ انہوں نے آگے بیان کر دی.پھر ضروری نہیں کہ یہ روایت صحیح ہو ایسی روایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں اور غلط بھی ہوتی ہیں ہم پابند نہیں کہ محض اس وجہ سے کہ ان کی طرف یہ روایت منسوب ہوتی ہے اسے درست تسلیم کر لیں اور قریش کی وجہ تسمیہ اسی قرش کو قرار دیں.میرا اپنا خیال ہے کہ قریش کا لفظ قَرَشَ سے نکلا ہے جس کے معنے ہیں ادھر ادھر سے جمع کیا.علامہ قرطبی جو سپین کےا یک بہت بڑے عالم گذرے ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہی معنے لکھے ہیں(تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا).میں تو پہلے بھی یہی بیان کرتا تھا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ علامہ قرطبی بھی اس کے یہی معنے کرتے ہیں.اب مجھے ان کا حوالہ مل گیا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان معنوں کا میں موجد نہیں بلکہ اس بارہ میں میرا علامہ قرطبی سے توارد ہو گیا ہے.علامہ قرطبی سپینش مفسر تھے.اور یہ ایک عجیب بات ہے جوخدا تعالیٰ کی کسی حکمت پر دلالت کرتی ہے (شاید اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ آئندہ زمانہ میں یورپ پھر اسی رنگ میں ترقی کرنے والا ہے) کہ سپین کے مسلمان مفسر بغداد کے مصنفوں کی نسبت بہت زیادہ معقول لکھنے والے ہیں.چوٹی کی کتابیں جو مختلف علوم و فنون سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب کی سب سپین میں لکھی گئی ہیں سوائے حدیث کے کہ حدیث وہاں نہیں گئی.اس لئے کہ حدیث کا علم انہی لوگوں سے نکلنا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے تھے اور وہ وہی تھے جو بغداد کے رہنے والے تھے یا دمشق کے رہنے والے تھے یہی وجہ ہے کہ سپین میں حدیث کی کوئی کتاب اس پایہ کی نہیں لکھی گئی جس پایہ کی کتابیں عرب کے یا اس کے پاس کے علاقوں میں لکھی گئی ہیں مگر باقی جتنے علوم ہیں ان پر سپین کے لوگوں کی طرف سے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں.مثلاً فلسفہ میں ابنِ رشد جو چوٹی کا فلسفی سمجھا جاتا ہے سپین کا رہنے والا تھا.تصوف میںجس شخص کو تمام دنیا چوٹی کے مقام پر سمجھتی ہے یعنی حضرت محی الدین صاحب ابن عربی، وہ ہسپانیہ کے رہنے والے تھے.فقہ کے متعلق جو آخری کلام سمجھا جاتا ہے وہ علامہ ابن حجر کا ہے اور علامہ ابن حجر بھی سپینش تھے.
Page 416
مفسرین میں قرطبی جو نہایت اعلیٰ درجہ کا مفسر ہے وہ بھی اندلسی ہے.اور علامہ ابوحیان جو بحرمحیط کے مصنف ہیں وہ بھی اندلسی ہیں میرے نزدیک پرانی تفسیروں میں سے بحرمحیط کے پایہ کی کوئی اورتفسیر نہیں.علامہ ابوحیان احمدیت سے پہلے ایک ہی شخص ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم میں ترتیب کا دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے اس دعویٰ کو ثابت کریں اور گو وہ ہمارے مقام تک نہ پہنچے ہوں مگر بہرحال وہ ایک ہی مفسر ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم بے جوڑ کتاب نہیں بلکہ سارے قرآن میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے.اسی طرح نحو اور ادب میں بھی وہ امام کہلاتے ہیں.بہرحال اندلسی مفسر قرطبی نے بھی یہی معنے کئے ہیں.افسوس ہے کہ ان کی ساری تفسیر چھپی نہیں.مصر میں ان کی تفسیر کی ابھی صرف دو تین جلدیں چھپی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں باقی تفسیر ابھی تک نہیں چھپی.مگر جو چھپی ہے وہ اتنی خطرناک طور پر غلط ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں.کوئی حدیث ایسی نہیں جو صحیح لکھی ہوئی ہو ساری کی ساری غلط ہیں.پہلے انسان اعتبار کر کے حدیث نقل کرلیتا ہے مگر بعد میں وہ غلط نکل آتی ہے.معلوم ہوتا ہے اس تفسیر کو چھاپتے وقت احتیاط سے کام نہیں لیا گیا.بہرحال قرطبی نے بھی یہی کہا ہے کہ قریش قَرَشَ سے نکلا ہے جس کے معنے ہیں ادھر ادھر سے جمع کیا.ذبیانی نے بھی یہ معنے کئے ہیں مگر ساتھ ہی د وسرے معنے بھی لکھ دیئے ہیں.قریش دراصل نام ہے بنو نضر بن کنانہ کا.جیسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے.چنانچہ آپ سے جب سوال کیا گیا کہ قریش کن کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اَلْقُرَیْشُ مِنْ وُلْدِ النَّضْـرِ.نضر کی جو اولاد ہے وہ قریشی کہلاتی ہے.اسی طرح احادیث میں آتا ہے قَالَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللہَ اصْطَفٰی کِنَانَۃَ مِنْ بَنِی اسْـمٰعِیْلَ وَاصْطَفٰی مِنْ کِنَانَۃَ قُرَیْشًا وَاصْطَفٰی مِنْ قُرَیْشٍ بَنِیْ ہَاشَـمٍ وَاصْطَفَانِیْ مِنْ بَنِیْ ہَاشَـمٍ (سراج منیر تفسیر سورۃ قریش) یعنی اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو بنی اسمٰعیل میں سے فضیلت دی.کنانہ میں سے قریش قبیلہ کو فضیلت دی.قریش قبیلہ میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو فضیلت دی اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی.اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بنوکنانہ قرار دیا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مِنْ وُلْدِ النَّضْـرِ(مجمع البیان زیر آیت لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ).دراصل کنانہ کے کئی بیٹے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح فرما دی کہ ان میں سے صرف نضر کی اولاد قریش کہلاتی ہے ساری اولاد نہیں.بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قریش صرف مالک بن نضر کی اولاد کا نام ہے.بلکہ بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ نضر کی اولاد میں سے صرف مالک کی ہی اولاد چلی ہے باقی کی نہیں.مگر یہ تاریخی شعبدہ بازی ہے جو مذہبی جھگڑوں
Page 417
سے تعلق رکھتی ہے چنانچہ جب ہم روایتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیعوں کی روایت ہے.چونکہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمر ؓ مالک بن نضر کی اولاد نہیں بلکہ ایک دوسرے بیٹے کی اولاد ہیں.اس لئے ان کو قریش میں سے نکالنے کے لئے ان کے دشمنوں نے یہ روایت گھڑی ہے وہ اس روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْاَئِـمَّۃُ مِنْ قُرَیْشٍ(مسند احمد بن حنبل مسند ابو برزۃ) مگر ابوبکرؓ اور عمرؓ دونوں قریش میں سے نہیں.چنانچہ انہوں نے اس قسم کی روایتیں گھڑ کر شامل کر دیں کہ نضر کی اولاد میں سے صرف مالک کی اولاد چلی ہے اس لئے یہ قریشی ہی نہیں ہیں.پس یہ حدیث شیعہ سنی جھگڑے کے نتیجہ میں پیدا ہوئی ہے.حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ قصی بن حکیم بن نضر کی اولاد تھے(المعارف اخبار ابی بکر رضی اللہ عنہ و عـمر بن الخطاب).پس ان کو قریشیوں میں سےنکالنے کے لئے یہ روایت وضع کی گئی ہے کہ قریش صرف مالک بن نضر کی اولاد کا نام ہے.حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے تو حضرت اسمٰعیلؑ کو خانہ کعبہ میں اس لئے بٹھایا تھا کہ وہ خانۂ کعبہ کی حفاظت کریں.لیکن حضرت اسمٰعیلؑ کی اولاد میں آگے یہ جوش دیرتک قائم نہ رہا جیسے آج بعض سید چور بھی ملتے ہیں اور ڈاکو بھی ملتےہیں.کچھ نسل تک تو انہوں نے تو اس وعدہ کو یاد رکھا لیکن اس کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گئے اور حضرت اسمٰعیلؑ کی اولاد سارے عرب میں پھیل گئی.بلکہ عرب کے علاوہ شام تک بھی چلی گئی.آخر قربِ زمانۂ نبویؐ میں قصی بن حکیم بن نضر کے دل میں خیال آیا کہ ابراہیمی وعدہ کو تو ہم پورا نہیں کر رہے ہمارے دادا نے تو یہ کہا تھا کہ تم یہاں رہو.اس گھر کی صفائی رکھو.خانۂ کعبہ کے حج اور طواف کے لئے جو لوگ آئیں ان کی خدمت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گذارو مگر ہم ادھر ادھر بکھر گئے اور اس خدمت کو جو ہمارے دادا نے ہمارے سپرد کی تھی بھول گئے.یہ خیال ان کے دل میں اتنے زور سے پیدا ہوا کہ انہوں نے بنو نضر کے اندر یہ تحریک شروع کی کہ آؤ ہم لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر مکہ میں جابسیں اور خانہ کعبہ کی خدمت کریں.یہ مناسب نہیں کہ ہم دنیوی اغراض کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وعدہ کو بھول جائیں اور جو نصیحت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی اس کی پروا نہ کریں.انہوں نے جب ہمارے سپرد یہ کام کیا تھا کہ ہم خانۂ کعبہ کی خدمت کریں تو ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم مکہ میں چلے جائیں اور خانۂ کعبہ کی خدمت کریں.چنانچہ ان کی قوم نے ان کی بات مان لی اور وہ سب مکہ میں اکٹھے ہوگئے.یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نےکی.وہ باہر بڑی بڑی اچھی چراگاہوں میں رہتے تھے، وہ تجارتیں بھی کرتے تھے، وہ زمینداریاں بھی کرتے تھے.وہ اور کئی قسم کے کاروبار میں بھی حصہ لیتے تھے مگر یک دم ساری قوم
Page 418
نے اپنی زمینیں چھوڑیں، گلہ بانی چھوڑی، زمینداری چھوڑی، تجارت چھوڑی اور ایک وادیٔ غیر ذی زرع میں جہاں آمدن کی کوئی صورت نہیں تھی آبیٹھے.میں سمجھتا ہوں اس قربانی کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی کہ ایک قوم کی قوم اپنے پیشے چھوڑ کر محض اس لئے ایک وادیٔ غیر ذی زرع میں آبیٹھی کہ ان کے دادا ابراہیمؑ نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم مکہ میں رہو اور جو لوگ یہاں حج اور طواف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے آئیں ان کی خدمت کرو.یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے کی.پس چونکہ یہ لوگ متفرق ہونے کے بعد پھر اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ میں جمع ہو گئے تھے تاکہ ابراہیمی وعدہ کو پورا کریں اس لئے ان کا نام قریش رکھا گیا.جیسا کہ میں بتا چکا ہوں قَرَشَ کے معنے جمع کرنے کے ہیں پس قریش وہ قبیلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے مکہ میں جمع کیا گیا اور اسی لئے ان کا نام قریش ہوا.انہیں اس لئے قریش نہیں کہتے تھے کہ وہ باقی تمام قبائل عرب پر غالب تھے اور قِرْش کی طرح ان کو کھا جاتے تھے.قریش کو عربوں میں یہ شہرت اور عزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زمانہ میں حاصل ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو یہ لوگ مجاوروں کی طرح وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور قبائلِ عرب پر ان کو کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا.پس قریش کے معنے ہیں وہ قبیلہ جو اردگرد سے اکٹھا کر کے قصی بن کلاب بن نضر نے مکہ میں آبٹھایا تھا یا یوں کہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ اولاد قریش کہلائی کیونکہ وہ اردگرد سے لا کر مکہ میں بیت اللہ کی خدمت کے لئے لا بٹھائی گئی تھی.میں اوپر بتا چکا ہوں کہ قریش کا نام قریش کیوں پڑا.میں نے بتایا ہے کہ اس بارہ میں میری تحقیق یہ ہے کہ ان کا یہ نام کسی سمندری جانور کی وجہ سے نہیںرکھا گیا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قصی بن کلاب کے وعظ کرنے پر اور یہ توجہ دلانے پر کہ چونکہ ہمارے دادا ابراہیمؑ نے ہمیں مکہ میں رہنے کا ارشاد فرمایا تھا اور ہمارے سپرد خانۂ کعبہ کی خدمت کی تھی ہمیں چاہیے کہ ہم اردگرد کے علاقوں کو چھوڑ کر مکہ میں جا بسیں اور وہیں اپنی زندگی بسر کریں.وہ مکہ میں آکر رہنے لگ گئے تھے.پس چونکہ وہ قصی بن کلاب بن نضر کے توجہ دلانے پر مختلف مقامات سے اٹھ کر مکہ میں جا کر بس گئے اس لئے وہ قریش کہلائے یعنی جمع شدہ لوگ.اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریش تو تصغیر کا صیغہ ہے اور معنے یہ ہیںکہ مکہ میں جمع ہو جانے والا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا ایک چھوٹا سا گروہ پھر کیا وجہ ہے کہ آلِ اسماعیل کو ایک چھوٹا سا گروہ یا چھوٹا سا ٹکڑا کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حکم تو سارے بنو اسمٰعیل کو تھا کہ وہ مکہ میں رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش کریں اور جو لوگ حج اور طواف کے لئے آئیں ان کی خدمت کریں.مگر چونکہ بنوکنانہ میں سے صرف نضر بن کنانہ کی اولاد مکہ میں آکر بسی اور چونکہ وہ سارے بنواسماعیل ؑ میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا اس لئے وہ قریش
Page 419
کہلائے یہ بتانے کے لئے کہ ہم تھوڑے سے آدمی ہیں جو اپنے داد اابراہیم کی بات مان کر یہاں جمع ہو گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جو لوگ خانۂ کعبہ کے حج کے لئے آئیں ان کی خدمت کریں.اور شاید اس نام میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دوسرے قبائل کو بھی مکہ میں جمع ہونے کی تحریک ہوتی رہے اور حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی باقی اولاد کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا رہے کہ جب ہم سے تھوڑے سے لوگ وہاں بس گئے ہیں اور انہوں نے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لیا ہے تو ہم بھی تو اولادِ ابراہیمؑ میں سے ہیں اگر ہم بھی وہاں جابسیں اور اپنے دادا کے حکم کو مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے.پس شاید اس تصغیر میں ایک یہ بھی حکمت ہو کہ اس نام سے باقی بنواسمٰعیل کےد ل میں تحریک ہوتی رہے اور وہ بھی اپنے دادا ابراہیمؑ کی بات کو مانتے ہوئے خدا تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لئے مکہ میں آبسیں.پس ممکن ہے کہ اس نام سے انہوں نے دوسرے قبائل کے اندر تحریک کرنے کی ایک صورت پیدا کی ہو اور مکہ میں ان کے جمع ہونے کےلئے ایک تحریک جاری کی ہو.غرض قصی بن کلاب کی تحریک پر یہ لوگ آئے اورمکہ میں بس گئے مگر ابتداء میں عرب کی توجہ حج کی طرف اتنی نہیں تھی کہ وہ مکہ میں کثرت سے آتے جاتے اور خانۂ کعبہ کی برکات سے مستفیض ہوتے.اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے دادا کی ہدایت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی پیشگوئیوں کے باوجود خانۂ کعبہ کو چھوڑ کر چلی گئی.اگر حاجی کثرت سے مکہ میں آتے ہوتے تو ان لوگوں کے رزق کے سامان پیدا ہوتےرہتے اور ان کو مکہ چھوڑنے کی مجبوری پیش نہ آتی.پس آلِ اسمٰعیل کا مکہ کو چھوڑ کر دوسرے عرب علاقوں میں پھیل جانا اس امر کا ثبوت ہے کہ اس وقت تک خانۂ کعبہ کے حج کا رواج عرب میں کم تھا اور بہت تھوڑے لوگ حج کے لئے آتے تھے.مجاوروں کو ہی دیکھ لو ان کا کام کتنا ذلیل ہے اسے دیکھ کر شرم آنے لگتی ہے مگر کیا وہ اس ذلیل کام کو بھی آسانی سے چھوڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں.باوجود اس کے کہ وہ ایک قابلِ نفرت کام میں اپنی زندگی کے دن بسر کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی اس کام سے ان کا جتنا رزق وابستہ ہوتا ہے چاہے وہ رزق ذلّت سے ہی آئے اسے وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے.پس اگر بنو اسمٰعیل نے مکہ چھوڑا تو یقیناً اس کے معنے یہ تھے کہ اس زمانہ میں بہت ہی کم لوگ حج کیا کرتے تھے اور ان کے گذارہ کی کوئی صورت نہیں تھی.اس لئے یہ لوگ مکہ سے نکلے اور تمام عرب میں پھیل گئے.قریش کی مکہ میں آباد ہونے کے لئے انتہائی قربانی جب قصی بن کلاب کی تحریک پر یہ لوگ مکہ میں جا بسے تو یہی دقّت ان کو پھر پیش آئی.وہ بس تو گئے مگر چونکہ حاجی بہت کم آتے تھے اور یہ لوگ وہیں مکہ میں رہتے تھے باہر کہیں آتے جاتے نہیں تھے.نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سخت تنگی اور عسر کی حالت میں مبتلا ہو گئے اور ان کے
Page 420
گذارہ کی کوئی صورت نہ رہی بلکہ بعض لوگوں کی تو فاقہ تک نوبت پہنچ گئی اور ان کے لئے اپنی عزت اور زندگی کا قائم رکھنا مشکل ہوگیا.مگر پھر بھی قریش کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے ان تمام صعوبتوں کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا اور اپنی زبان پر وہ ایک لمحہ کے لئے بھی حرفِ شکایت نہ لائے اوّل تو ان کی یہی بہت بڑی قربانی تھی کہ انہوں نےاپنے کام کاج چھوڑے، پیشوں کو ترک کیا، تجارتوں کو نظرانداز کیا، زمین داریوں سے منہ موڑا اور ایک وادیٔ غیرذی زرع میں جہاں روزی کا کوئی سامان نہ تھا، اہل وعیال کو لے کر رہنا شروع کر دیا.مگر پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ قریش کا مکہ میں بسنا کوئی ایسی قربانی نہیں جس کی تعریف کی جا سکے کیونکہ مکہ کی عزت لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ وہاں حج کے لئے آتے جاتے تھے اس لئے ممکن ہے وہ دولت یا عزت کی خواہش کی وجہ سے مکہ میں جا کر بس گئے ہوں.سو چونکہ یہ اعتراض پیدا ہو سکتا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے ان کی عزت ظاہر کرنے کے لئے پھر دوسری دفعہ ان کو قربانی کا موقع دیا.مکہ میں بسنے کی وجہ سے ان کے گذارہ کی کوئی صورت نہ رہی.حج کی طرف عربوں کو بہت کم توجہ تھی نتیجہ یہ ہو اکہ فاقوں کی وجہ سے جانوں کے اتلاف تک نوبت پہنچ گئی.یہ لوگ کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بےدین بھی تھے اور ان میں سینکڑوں قسم کی خرابیاں پائی جاتی تھیں لیکن اس قوم میں بعض غیر معمولی خوبیاں بھی تھیں.مکہ کے لوگوں میں سے جب کسی خاندان کے پاس کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو جاتا اور اس کی حالت غیر ہو جاتی.وہ دوست بھی جو ان کی حالت سے آگاہ ہوتے مدد سے لاچار ہوتے کیونکہ وہ خود بھی غریب ہی ہوتے تھے تو وہ فاقہ کش لوگ قصی پر اعتراض نہیں شروع کر دیتے تھے کہ اس نے ہمیں غلط تعلیم دی تھی ہم مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے.وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے بےوقوفی کی کہ ایسی جگہ آبسے جہاں روٹی کا کوئی سامان نہیں تھا بلکہ وہ خاندان اسی وقت اپنا خیمہ اٹھا کر مکہ سے ذرا باہر چلا جاتا (مکانوں کا رواج عرب میں بہت کم تھا بلکہ اب تک بھی بادیہ کے لوگ خیموں میں رہتے ہیں) اور مکہ سے دو تین میل پرے اپنا خیمہ لگا لیتا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں لے جاتا تا کہ اس کے رشتہ داروں، دوستوں اور محلہ والوں کو اس کی اس بری اور خراب حالت کا پتہ نہ لگے.اور وہیں وہ سب کے سب بھوکے مر جاتے(درّمنثور سورۃ قریش اٰیٰت ۱تا۴).میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کی قربانی ہے کہ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی.لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو وہ فوراً کسی دوسری جگہ جا کر اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دوسروں سے سوال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے اور صبر اور برداشت کی قوت کو بالکل کھو بیٹھتے ہیں.ہمارے صوفیاء نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شہر چھوڑ کر باہر جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گا وہ کھانا بھیج دے گا تو کھا لوں گا اور اگر نہ بھیجے گا تو فاقہ کروں گا.جب لوگوں کو
Page 421
معلوم ہوا کہ انہوں نے شہر سےباہر ڈیرے لگا لئے ہیں تو ان کی بزرگی اور تعلقات کی وجہ سے دوستوں نے ان کو باقاعدہ صبح و شام کھانا پہنچانا شروع کر دیا مگر ایک دفعہ ایسا اتفا ق ہوا کہ انہیں کھانا نہ پہنچا.شاید ان سے زیادہ تعلق رکھنے والے لوگ کہیں باہر چلے گئے تھے یا شاید ان میں سے ہر ایک نے یہ سمجھا کہ دوسرے نے کھانا بھیج دیا ہو گا.اور اس طرح کوئی شخص بھی کھانا نہ لایا.ایک وقت گذرا اور انہیں کھانا نہ ملا.دوسرا وقت آیا تب بھی کھانا نہ آیا.اس کے بعد تیسرا وقت آگیا مگر انہیں پھر بھی کھانا نہ پہنچا.تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد پانچواں اور پانچویں کے بعد چھٹا فاقہ ان پر آگیا.جب چھ فاقے ہو گئے تو اب ان کے لئے برداشت کرنا مشکل ہو گیا وہ کسی طرح گرتے پڑتے شہر میں آئے اور اپنے کسی دوست کے ہاں جا کر اس سے خواہش کی کہ وہ انہیں کچھ کھانے کو دے.اس نے تین روٹیاں اور ان پر کچھ سالن رکھ کر پیش کیا.انہوں نے روٹیاں اٹھائیں سالن لیا اور باہر جنگل کو چل پڑے.کچھ دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ گھر کے مالک کا کتا بھی ان کے پیچھے چلا آرہا ہے.انہیں خیال آیا کہ اس کتے کا بھی ان روٹیوں پر حق ہے.اس پر انہوں نے ایک روٹی لی اس پر سالن کا تیسرا حصہ رکھا اور کتے کے آگے ڈال دیا.اس نے جلدی جلدی روٹی کھائی اور پھر ان کے پیچھے چل پڑا.وہ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ پھر ان کو خیال آیا کہ کتا تو ابھی پیچھے چلا آرہا ہے معلوم ہوتا ہے ابھی اسے سیری نہیں ہوئی.میں سمجھتا ہوں کتا شاید اس لئے ان کے پیچھے گیا ہو گا کہ وہ اس کے مالک کے دوست تھے اور کتا ان کو اکثر آتے جاتے دیکھتا ہو گا.کتا جہاں اپنے آقا کے ساتھ محبت رکھتا ہے وہاں وہ اپنے آقا کے ساتھ ملنے والوں کو بھی خوب پہچانتا ہے بہت ہی ذہین جانور ہے.مگر انہوں نے تصوّف کے اثر کے نیچے یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنا حق مانگتا ہے.چنانچہ انہوں نے کتے کو دیکھ کر کہا بے شک تیرا حق مجھ سے زیادہ ہے تو تُو ہر وقت وہاں بیٹھا رہتا ہے مگر میں تو کبھی کبھار جاتا ہوں.یہ کہہ کر انہوں نے دوسری روٹی لی اس پر بقیہ سالن کا نصف حصہ رکھا اور اسے کتے کے آگے ڈال دیا.کتے نے وہ روٹی بھی کھا لی مگر پھر بھاگ کر ان کے پیچھے چل پڑا.اب جو کتا ان کے پیچھے چلا تو انہیں بہت غصہ آیا اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی باتیں کرنے لگتا ہے.ہمارے ملک میں بیل چلانے والے بیل سے باتیں کرتے ہیں.گدھے چلانے والے گدھوں سے باتیں کرتے ہیں.اِکّے والے آدھی باتیں سواری سے کرتے ہیں اور آدھی باتیں گھوڑے سے کرتے ہیں.کبھی کہتے ہیں شاباش قدم اٹھائے چلا جا میں تجھے خوب گھاس کھلاؤں گا.کبھی نہیں چلتا تو غصہ میں اسے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں.اسی طرح جب انہوں نے بھی دیکھا کہ کتا ابھی تک پیچھے چلا آرہا ہے تو انہوں نے غصہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا بے حیا دو روٹیاں تو میں ڈال چکا ہوں مگر پھر بھی تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا.انہوں نے یہ
Page 422
بات کہی ہی تھی کہ ان پر کشفی حالت طاری ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہی کتا ان کے سامنے کھڑا ہے.کشف میں جانور بھی باتیں کر لیتے ہیں.زمین بھی بات کر لیتی ہے.لکڑی بھی بات کر لیتی ہے اس لئے کتے کی بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے انہوں نے دیکھا کہ کتا ان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ بے حیا میں ہوں یا تم.میں جس انسان کے دروازہ پر بیٹھا ہوں اسے میں نے کبھی نہیں چھوڑا خواہ فاقوں پر فاقے کیوں نہ آئیں.مگر تم محض خدا کے لئے جنگل میں جا بیٹھے تھے لیکن چند فاقے ہی آئے تھے کہ شہر کی طرف اٹھ بھاگے.اس نے اتنا کہا اور کشفی حالت جاتی رہی.انہوں نے تیسری روٹی اور باقی سالن بھی کتے کے آگے ڈال دیا اور خود خالی ہاتھ جنگل کی طرف چل پڑے.وہاں پہنچے ہی تھے کہ تھوڑی دیر میں ان کےد وست اور کئی دوسرے لوگ کھانا لئے ہوئے آپہنچے اور ان سے معذرت کرنے لگے کہ پچھلے چند دنوں وہ اس خدمت سے محروم رہے.ان بزرگ نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرا امتحان لیا گیا تھا.اب اس قصہ کو مکہ کے لوگوں کے حالات سے مقابلہ کر کے دیکھو وہ لوگ مشرک تھے لیکن ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت بننے کی قابلیت خدا تعالیٰ پیدا کر رہا تھا.یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ مکہ سے کچھ فاصلہ پر خیمے لگا لیتے اور اپنے بیوی بچوں سمیت وہیں بھوک سے تڑ پ تڑپ کر مر جاتے مگر مکہ کو نہ چھوڑتے تھے اور نہ دوسرے لوگوں سے سوال کرتے.اس سے ایک طرف تو ان کے اس جوش کا پتہ لگتا ہے جو ان کے دلوں میں خانۂ کعبہ کی خدمت کے متعلق تھا اور دوسری طرف ان کی قناعت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر بار نہیں بنتے تھے.کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے.الگ تھلگ ایک خیمہ میں پڑے رہتے اور وہیں سب کے سب مر جاتے.قریش کی قربانی میں ہماری جماعت کے لئے نمونہ میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت جو اس امر کی مدعی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تعلیم پر ایمان رکھتی اور اس کے نور کی حال ہے اس کے افراد کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے.خصوصاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد اور آپ کے خاص اتباع کی اولاد کو میں ان کے اس فرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں.میں دیکھتا ہوں کہ دین کے لئے قربانی اورا یثار کا وہ مادہ ابھی تک ان میں پیدا نہیں ہوا جو احمدیت میں داخل ہونے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد ان میں پایا جانا چاہیے تھا.ان کا قدم نہایت سست ہے اور ان کے اندر قربانی اور ایثار کا مادہ ابھی بہت کم ہے یقیناً اس معیار کے ساتھ ہم کبھی بھی دنیا پر غالب نہیں آسکتے جب تک ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں سمجھ لیتا کہ وہ غرض جس کے لئے وہ اس سلسلہ میں شامل ہوا ہے اور وہ مقصد جس کے لئے اس نے بیعت کی ہے وہ دوسری تمام اغراض اور
Page 423
دوسرے تمام مقاصد پر مقدّم ہے اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اپنےا یمان کا کوئی اچھا نمونہ دکھایا ہے.بلکہ میرے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کے لئے تو ایسے کام کرنا جن سے دین کی خدمت میں روک پیدا ہو قطعی طور پر ناجائز ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ ویسا ہی دنیادار شخص ہے جیسے کوئی اور لیکن دوسروں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے اندریہ مادہ ہونا چاہیے کہ جب دین کی طرف سے انہیں آواز آئے وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر فوراً چلے آئیں اور اپنے آپ کو دینی خدمات میں مشغول کر دیں.اب اگر وہ دنیا کا کام کرتے ہیں تو اس لئے کہ ابھی دین کو ان کی ضرورت پیش نہیں آئی.لیکن اگر ضرورت پیش آجائے تو پھر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیعت کے وقت انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم دین کو دنیا پر مقدّم رکھیں گے.اس دین کو دنیا پر مقدّم رکھنے کے عہد کے آخر کوئی معنے تو ہونے چاہئیں.اس کے تم کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ معنے کر لو آخر کسی نہ کسی چیز کو تمہیں بہرحال اپنے کاموں پر مقدّم رکھنا پڑے گا.اگر اس عہد میں تم مال شامل کرو تو تمہیں مال پر دین کو مقدّم رکھنا پڑے گا.اگر جان شامل کرو تو تمہیں جان پر دین کو مقدّم رکھنا پڑے گا.اگر خدمت شامل کرو تو تمہیں ہر قسم کی خدمت پر دین کو مقدّم رکھنا پڑے گا.بہرحال کوئی نہ کوئی مفہوم تمہیں اس اقرار کا تسلیم کرنا پڑے گا اور جب یہ اقرار ہر احمدی نے کیا ہے تو ہماری جماعت کے افراد کو سوچنا چاہیے کہ اس اقرار کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدّم رکھتے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے احمدی موجود ہیں جو سو میںسے ۵۱ روپے دین کے لئے خرچ کرتے ہوں.مقدّم کے معنے تو یہ ہوتے ہیں کہ میں اور کاموں پر اس کام کو ترجیح دیتا ہوںاگر انہیں سو روپیہ اپنے اخراجات کے لئے ملتا ہے اور وہ دیانت داری کے ساتھ اپنے تمام کاموں پر دین کو مقدّم سمجھتے ہیں تو اس کا ثبوت اسی طرح مل سکتا ہے کہ وہ سو میں سے ۵۱ روپے دین کے لئے خرچ کرتے ہوں.مگر کیا وہ ایسا کرتے ہیں؟ کیا وہ دن رات کے ۲۴ گھنٹوں میں سے تیرہ گھنٹے دین کے کاموں پر صرف کرتے ہیں؟ یا قربانی اور ایثار کے لحاظ سےوہ اپنے بیوی بچوں اور دوسری چیزوں پر دین کو مقدّم کرتے ہیں؟ یا وطن کے لحاظ سے وہ دین کو دنیا پر مقدّم سمجھتے ہیں؟ یا جان کے لحاظ سے وہ دین کو دنیا پر مقدّم سمجھتے ہیں؟ آخر کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے جس کے لحاظ سے وہ کہہ سکتے ہوں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدّم کر رہے ہیں.اگر ہر احمدی اس نقطۂ نگاہ سے غور کرے اور اسے اپنے اندر ایک بات بھی ایسی نظر نہ آئے جس میں وہ دین کو دنیا پر مقدّم کر رہا ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ محض منافقت کی بات ہے کہ وہ دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدّم کرتا ہوں مگر عمل یہ ہے کہ وہ کسی ایک چیز کے لحاظ سے بھی دین کو دنیا پر مقدّم نہیں کرتا.آخر کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے جس کے متعلق وہ کہہ سکے کہ میں فلاں چیز کے لحاظ سے دین کو دنیا پر مقدّم کر رہا ہوں.
Page 424
اور اس عہد کا کوئی نہ کوئی مفہوم تو ہونا چاہیے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ عہد ہم سے صرف اتنا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم کسی ایک پہلو میں دین کو دنیا پر مقدّم کریں بلکہ ہر بات میں اور اپنے ہر کام میں ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کو دنیا پر مقدّم کریں.مگر سوال تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہر کام میں دین کو دنیا پر مقدّم نہیں کر سکتا اسے کم از کم یہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی ایک کام میں ہی دین کو دنیاپر مقدّم رکھے تاکہ وہ کہہ سکے کہ میں اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.یہ کوشش خواہ وہ مال کے لحاظ سے کرے، خواہ تجارت کے لحاظ سے کرے، خواہ پیشہ کے لحاظ سے کرے، خواہ وطن کی محبت کے لحاظ سے کرے، خواہ ملازمت کے لحاظ سے کرے، خواہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے تعلقات کے لحاظ سے کرے، خواہ عبادت کے لحاظ سے کرے، خواہ قربانی اور ایثار کے لحاظ سے کرے، بہرحال کوئی ایک چیز تو ایسی ہونی چاہیے جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہو اور کہہ سکتا ہو کہ جن کاموں کا مجھے موقع ملا ہے ان میں مَیں نے دین کو دنیا پر مقدّم کر لیا ہے اور جو باقی کام ہیں ان میں بھی میں پوری طرح تیار ہوں کہ اس عہد کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں.لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دعویٰ ایمان محض ایک منافقانہ فعل ہے جو اس کے کسی کام نہیں آسکتا.تم قریش کے اس واقعہ پر غور کرو اور دیکھو کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ سچے دین کے حامل نہیں تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بُت پرست تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بے دین تھے انہوں نے کتنی عظیم الشان قربانی کی.یہ لوگ اپنی قوم پر بوجھ نہیں بنے انہوں نے کہا ہم خدا کے لئے آئے تھے ہماری قوم کا کیا حق ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے.وہ خیمہ اٹھا کر مکہ سے باہر چلے جاتے.باپ کے سامنے اس کا بیٹا مرتا، ماں کے سامنے اس کی بیٹی مرتی، بیوی کے سامنے اس کا خاوند مرتا، بچوں کے سامنے ان کا باپ مرتا، دوست کے سامنے دوست اور رشتہ دار کے سامنے رشتہ دار مرتا مگر کیا مجال کہ ان کی زبان پر کوئی شکایت آتی.کیا مجال کہ وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے.اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا.وہ کسی معجزہ کو دیکھ کر وہاں نہیں آئے تھے، وہ کسی نشان کو دیکھ کر وہاں نہیں آئے تھے، وہ کسی تازہ تعلیم پر ایمان لا کر وہاں نہیں آئے تھے، دو ہزار سال پہلے ان کے دادا ابراہیمؑ نے ایک بات کہی تھی اور وہ اپنے دادا کے وعدہ کے مطابق اس سرزمین میں آبسے.ان پر فاقے آئے مگر انہوں نے اس جگہ کو نہ چھوڑا.ان میں فاقہ سے موتیں ہوئیں مگر انہوں نے اس جگہ کو نہ چھوڑا.انہوں نے سالاہا سال غربت اور تنگی اور افلاس میں اپنی زندگی کے دن بسر کئے.ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا ان کے پاس گذارہ کا کوئی سامان نہیں تھا مگر انہوں نے کہا ہم اس مقام کو اب نہیں چھوڑ سکتے.ہم مٹ جائیں گے ہم ایک ایک کر کے فنا ہو جائیں گے مگر ہم مکہ کو چھوڑ کر کہیں باہر نہیں جائیں گے.یہ اتنی عظیم الشان
Page 425
قربانی ہے کہ یقیناً اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی.یمن میں تجارت کے قافلے بھجوانے کی ابتداء بہرحال اسی طرح مکہ میں ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ہاشم بن عبد مناف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑدادا تھے ان کا وقت آگیا.جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو سمجھا کہ اس طرح تو قوم فنا ہو جائے گی.انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں تقریر کی کہ جو طریق تم نے ایجاد کیا ہے یہ اپنی ذات میں تہوّر کے لحاظ سے تو بڑا اچھا ہے مگر اس طرح وہ کام پورا نہیں ہو گا جس کے لئے تم لوگ مکہ میں آئے ہو.اگر یہی طریق جاری رہا اور تم میں سے اکثر مر گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مکہ خالی ہو جائے گا بے شک جوش و خروش اور عزم کی پختگی کے لحاظ سے یہ کام ایسا شاندار ہے کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے مگر عقل کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں کوئی ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ ہم سب لوگ مکہ میں بھی رہیں اور اس قسم کی موت بھی ہم میں واقعہ نہ ہو.غالباً ان کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہو گا کہ اگر اس طریق کو جاری رہنے دیا گیا تو دوسری قوموں پر اس کا برا اثر پڑے گا اور وہ کہیں گی یہ لوگ خدا کے لئے مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے مگر بھوکے مر گئے.پس اس طرح خدا کا احترام کم ہو جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا.ہمیں اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہمارا اعزاز دنیا میں قائم ہو اور دوسرے عرب قبائل سے ہماری حالت اچھی ہو.مکہ والوں نے ہاشم کی بات سن کرکہا آپ جو تدبیر بتائیں ہم اسے ماننے کے لئے تیار ہیں.آپ نے فرمایا میری تجویز تو یہ ہے کہ ہم لوگ رہیں تو مکہ میں ہی مگر اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لئے تجارت شروع کر دیں.یوں بھی اپنی ذاتی اغراض کے لئے ہم بعض دفعہ سفر کر لیتے ہیں اگر آئندہ ہم بعض سفر محض تجارت کی خاطر کریں تو اس سے ہماری گری ہوئی حالت بہت کچھ سدھر جائے گی اور ہماری پریشانی دور ہو جائے گی.(درمنثور سورۃ قریش اٰیٰت ۱تا۴) زراعت کی تجویز آپ نے اس لئے نہ کی کہ مکہ میں زراعت کی کوئی صورت نہیں تھی دوکانداری کی تجویز آپ نے اس لئے نہ کی کہ دوکاندار کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ رات دن دوکان پر بیٹھا رہے.آپ نے سمجھا کہ اگر لوگوں نے دوکانداری شروع کر دی تو خدمت کعبہ کا وہ موقع جو اب انہیں مل رہا ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے چنانچہ آپ نے یہ تجویز کی کہ قوم کا روپیہ لے کر ہر سال دو سفر کئے جائیں.ایک سفر سردی کے موسم میں کیا جائے جو یمن کی طرف ہو اور ایک سفر گرمی کے موسم میں کیا جائے جو شام کی طرف ہو.شام بوجہ سرد مقام ہونے کے گرمی کے سفر کے لئے موزوں تھا اور یمن بوجہ گرم مقام ہونے کے سردی کے سفر کے لئے موزوں تھا.آپ نے تجویز کیا کہ ہر سال اہل مکہ کے نمائندہ قافلے یہ دو سفر محض تجارت کی غرض سے کیا کریں اور تجارت بھی قوم کے لئے کریں.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
Page 426
ہاشم بن عبد مناف نے دنیا میں یا کم سے کم عرب میں سب سے پہلے کمپنی سسٹم جاری کیا ہے.یوں تو تاجر دنیا میں ہمیشہ تجارت کیا ہی کرتے ہیں.زید تجارت کی غرض سے باہر جاتا اور سودا لے کر آجاتا ہے تو پھر اسے زیادہ مہنگے داموں پر وہ فروخت کر دیتا ہے.مگر یہ کہ سفر کسی فرد کا نہ ہو بلکہ قومی طور پر تمام قبیلہ کا مشترکہ سرمایہ لے کر سفر کیا جائے اس کی ابتداءکم سے کم عرب میں ہاشم بن عبد مناف سے ہی ہوئی ہے.لوگوں نے کہا بہت اچھا ہمیں منظور ہے چنانچہ قافلے جانے لگے.جب بھی کوئی قافلہ جاتا تو ہر شخص دس۱۰ بیس۲۰ پچاس۵۰ یا سو۱۰۰ روپیہ جتنا دینا چاہتا قافلہ والوں کے سپرد کر دیتا.پھر ان میں سے ایک کو رئیس بنا دیا جاتا.اور باقی لوگ اہلِ مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر اس سفر پر روانہ ہو جاتے.امرا جن کی حالت کچھ اچھی تھی وہ بعض دفعہ تجارت کی غرض سے اپنے غلام بھی ان سفروں میں بھیج دیا کرتے تھے.ان کا طریقِ تجارت یہ تھا کہ وہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے لیتے تھے جو ان کی نظروں میں متبرّک ہوتی تھیں اور جہاں جہاں عرب قبائل میںسے گذرتے وہاں مکہ کے تبرکات انہیں دیتے جاتے.مثلاً آبِ زمزم کے کچھ مشکیزے بھر کر اپنے ساتھ رکھ لیتے چونکہ عرب قبائل کو خانۂ کعبہ سے بہت عقیدت تھی اس لئے جب انہیں گھر بیٹھے آبِ زمزم میسر آجاتا یا اسی طرح کی بعض اور چیزیں مل جاتیں تو وہ بہت خوش ہوتے اور قریش کو نہایت ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے.اسی طرح اور بھی کئی چیزیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے.مثلاً مکہ میں لوہارے کا کام اچھا ہوتا ہے وہ لوہے کی تیار شدہ چیزیں لے لیتے.اسی طرح کھجوریں اپنے ساتھ رکھ لیتے اور یہ سب چیزیں رستہ میں فروخت کرتے جاتے.پھر جہاں عرب قبائل میں ٹھہرتے اور دیکھتے کہ وہاں کوئی چیز ایسی ہے جو شام میں اچھے داموں پر فروخت کی جا سکتی ہے تو وہ ان قبائل سے ایسی چیزیں خود خرید لیتے اور شام میں جا کر فروخت کر دیتے پھر جب شام سے آتے تو وہاں سے دو قسم کا مال خرید لیتے کچھ تو مکہ والوں کے لئے اور کچھ راستہ میں آنے والے عرب قبائل میں فروخت کرنے کے لئے.اس طرح ان کو نفع بھی حاصل ہوتا اور شام اور دوسرے عرب علاقوں کا مال بھی مکہ میں آجاتا.اسی طرح سردیوں میں وہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے.مکہ اور یمن کے درمیان بھی بڑا لمبا فاصلہ تھا اور اس راستہ پر بھی مختلف عرب قبائل آباد تھے اس سفر میں بھی وہ تمام لوگوں کو مکہ کے تحائف دیتے اور ان سے عمدہ عمدہ چیزیں خریدتے ہوئے یمن پہنچ جاتے اور یمن میں تمام مال فروخت کر کے وہاں کی مصنوعات اور غلّہ وغیرہ کچھ مکہ والوں کے لئے اور کچھ رستہ کے عرب قبائل میں فروخت کرنے کےلئے لے آتے.نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال میں ہی مکہ کی دولت سارے عرب سے زیادہ ہو گئی.ان کا یہ بھی طریق تھا کہ جب قافلہ واپس آتا تو ہر آدمی جس کا اس تجارت میں حصہ ہوتا تھا وہ اپناآدھا حصہ غرباء کے لئے نکال دیتا تھا.مثلاً ایک
Page 428
غربت زیادہ ہے اس لئے یہاں کی عمر پہلے ۲۲ سال تھی اب ۲۸ سال کے قریب قریب سمجھی جاتی ہے.اگر ہم عربوں کی ایک نسل کی عمر ۳۰ سال فرض کر لیں تو یہ تحریک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی سوا دو سو سال پہلے شروع ہوئی ہے.حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے درمیان کوئی ۲۲.۲۳ سو سال کا فرق تھا.میں نے بتایا تھا کہ یہ اندازہ ۲۲ سو سے ۲۸سو سال تک سمجھا جاتا ہے اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا اندازہ رکھ لیں جو ۲۲ سو سال کا ہے اور اس میں سے یہ سوا دو سو سال نکال دیں تو باقی دو ہزار سال رہ گئے.یہ دو ہزار سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں قوم اپنا فرض بھولی رہی دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جوں جوں اوپر کی نسل کی طرف جائیں ماں باپ کی یاد اولاد کے دلوں میں زیادہ قائم ہوتی ہے اور جوں جوں نیچے کی طرف آئیں یہ یاد کم ہوتی چلی جاتی ہے.اس قاعدہ کے مطابق حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے زمانہ کا قرب جس نسل کو حاصل تھا اسے قدرتاً وہ وعدے زیادہ یاد ہونے چاہیے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئے.کیونکہ دنیا میں طریق یہی ہے کہ باپ کو بیٹا زیادہ یاد رکھتا ہے پوتا اس کی یاد کو کم کر دیتا ہے اور پڑپوتا اس کی یاد کو اور بھی کم کر دیتا ہے یہاں تک کہ چار پانچ پشت میں تو اولاد اپنے دادا پڑدادا کو بالکل ہی بھول جاتی ہے.اور اگر اس سے بھی زیادہ عرصہ گذر جائے تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا.چنانچہ تمام بڑی بڑی قوموں کو دیکھ لو سب میں یہی کیفیت نظر آئے گی مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہؓ کی اولاد نے جو ابتداء میں قربانیاں کیں وہ کتنی حیرت انگیز ہیں مگر اب سادات کو دیکھ لو ان کی کیا حالت ہے.ان میں سے اکثر ایسے ملیں گے جو اسلام سے کوسوں دور ہیں حالانکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہیں.پھر ہماری اپنی قوم کو دیکھ لو.چینی ترکستان سے باتو خان جو مغلوں کا ایک پڑدادا تھا اٹھااور طوفان کی طرح تمام یورپ پر پھیلتا چلا گیا(پنجاب کے مغل قبائل زیر عنوان باتوخان).دوسری طرف جتلائی خان مشرق میں چینی سمندر کے کناروں تک پر قابض ہو گیا(اردو دائرہ معارف زیر لفظ قبلائی).اگر ایک طرف جاپان کے کناروں تک ہماری قوم پہنچی تو دوسری طرف یورپ کو بھی اس نے روند ڈالا.مگر اب کئی مغل ایسے نظر آئیں گے جو دشمن کا مقابلہ تو الگ رہا خطرہ سامنے دیکھ کر چیخ مار کر بھاگ جائیں گےاور اپنے باپ دادوں کے کارنامے انہوں نے یکسر بھلا دیئے ہیں.اسی طرح پٹھان آئے تو وہ کس طرح سارے ہندوستان میں پھیل گئے مگر اب سمٹ سمٹا کر وہ پٹھان ایک چھوٹے سے علاقہ میں رہ گئے ہیں.اگر قربانی اور ایثار کا ان میں وہی مادہ رہتا جو ان کے باپ دادا میں تھا تو یہ انقلاب کیوں پیدا ہوتااور کیوں وہ حاکم ہونے کے بعد محکوموں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتے.غرض طبعی طریق کو اگر مدّ ِنظر رکھا جائے تو شروع زمانہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام کا اثر ان کی قوم پر زیادہ ہونا چاہیے
Page 429
تھا اور دو ہزار سال کے بعد تو ایسی جاہل اور اَن پڑھ قوم میں سے ان کا ذکر بالکل مٹ جانا چاہیے تھا مگر ہو ایہ کہ عین دو ہزار سال کے بعد پھر ان میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ اپنے دادا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مکہ میں آبسے.وہ بھوکے بھی رہے، وہ ننگے بھی رہے، وہ تکلیفیں بھی برداشت کرتے رہے مگر انہوں نے مکہ کو نہ چھوڑا.اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا اتفاق تھا جس نے دو ہزار سال کے بعد قوم میں خانۂ کعبہ کے گرد بسنے کا پھر احساس پیدا کر دیا.علم النفس کے ماتحت اگر ہم غور کریں تو دوہزار سال کے بعد یہ ذکر قوم میں سے بالکل مٹ جانا چاہیے تھا مگر ہوا یہ کہ دو ہزار سال کے بعد یک دم ان میں ایک شخص پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم کو پھر مکہ میں جمع ہو جانا چاہیے اور اولادِ اسمٰعیل میں سےایک قبیلہ باوجود ہر قسم کے مخالفانہ حالات کے مکہ میں بیٹھ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی خدمت اور مکہ کی حفاظت کا کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کام کو اتنی محبت اور اتنے پیار سے سر انجام دیتے ہیں کہ وہ بھوکے مرتے ہیں.ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے تڑپ تڑپ کر جان دیتے ہیں.ان کی بیویاں اور ان کی بیٹیاں مرتی ہیں مگر وہ مکہ کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے.اتنا شدید احساس دو ہزار سال گذرنے کے بعد ان لوگوں میں کیوں پیدا ہوااور پھر اسی قبیلہ کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا جس میںسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا ایک معمولی غور سے بھی یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ یہ قدرت کی ایک انگلی تھی جس نے قوم کو اشارہ کیا کہ جس بات کے لئے تمہارے باپ دادا نے اس مکہ کو آباد کیا تھا اس کا وقت اب بالکل قریب آرہا ہے جاؤ اور مکہ میں رہو.ورنہ یہ اتفاق کس طرح ہو سکتا ہے کہ دو ہزار سال ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک بڑی قوم کا صرف وہی ٹکڑا مکہ میں جمع ہوتاجس میں سے آنے والے موعود نے پیدا ہونا تھا.دشمن کہہ سکتاہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کر دیا.مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ اس جھوٹے کی آمد سے پہلے تمام قوم چاروں طرف سے اکٹھی ہو کر مکہ میں آجاتی ہے اور اس لئے آتی ہے کہ ہمارے دادا ابراہیم ؑ نے کہا تھا کہ تم اس مقام پر رہو اور اسے آباد رکھو کہ یہ عالمگیر مذہب کا مرکز بننے والا ہے یہ عظیم الشان تغیّر جو یک دم بنو اسمٰعیل میں پیدا ہو ااور جس نے ان میں تہلکہ ڈال دیا بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وعدہ کےمطابق ہوا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ١ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ( البقرۃ:۱۳۰).اےمیرے رب ان مکہ والوں میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو وہ انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، تیری کتاب کا علم ان کو دے حکمت کی باتیں ان کو سکھائے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے اس دعائے ابراہیمی سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رسول
Page 430
مکہ میں آئے گا اور مکہ کے رہنے والوں سے سب سے پہلے کلام کرے گا اگر مکہ آباد نہ ہوتا تو وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا کی دعا کس طرح پوری ہوتی اور وہ کون سے لوگ تھے جن میں یہ رسول مبعوث ہوتا.اسی طرح ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے.اگر مکہ آباد نہ ہوتا تو وہ کون لوگ تھے جن کو کتاب اور حکمت سکھائی جاتی.پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ رسول ان کو پاک کرے.ا گر وہاں کوئی آدمی ہی نہ ہوتا تو اس رسول نے پاک کن کو کرنا تھا وہ تو خس کم جہاں پاک کا پہلے ہی مصداق بن چکے تھے.اگر مکہ آباد نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ چار دعائیں کی تھیں ان میں سے ایک بھی پوری نہ ہو سکتی.پس یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ جو کچھ ہوا الٰہی سکیم اور اس کے منشاء کے مطابق ہوا.دشمن کہہ سکتا ہے کہ محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جھوٹا دعویٰ کر دیا مگر اس امر کو کون اتفاق کہہ سکتا ہے کہ دو ہزار سال تک ایک قوم ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے.وہ ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ کی تمام پیشگوئیوں کو فراموش کر دیتی ہے مگر جب زمانۂ محمدؐی قریب آتا ہے تو یک دم اس قوم میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے.وہ کہتی ہے ہم سے یہ کیا بے وقوفی ہوئی کہ ہم ادھر ادھر پھرتے رہے ہمارے دادا نے تو ہم سے کہا تھا کہ مکہ میں رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو.ہمارے دادا نے تو کہا تھا کہ تمہاری تمام ترقی مکہ میں رہنے سے وابستہ ہے.مگر ہم کہیں کے کہیں پھرتے رہے.اور وہ پھر مکہ میں آکر بس جاتی ہے.اس لئے نہیں کہ مکہ میں کوئی کارخانہ کھل گیا تھا، اس لئے نہیں کہ وہاں تجارتیں اچھی ہوتی تھیں، اس لئے نہیں کہ وہاں زراعت اچھی تھی بلکہ صرف اس لئے کہ ابراہیمؑ نے انہیں ایک بات کہی تھی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لئے وہاں اکٹھے ہو گئے.پس یہ اتفاق نہیں بلکہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کے منشا اور اس کے ازلی فیصلہ کے مطابق ہوا.پھر میرے نزدیک بالکل ممکن ہےکہ اس اجتماع میں یہودی اور نصرانی روایات کا بھی دخل ہو کیونکہ قوم کو دوبارہ بسانے والے قصی تھے جن کے تعلقات نصاریٰ اور یہود سے تھے.تعجب نہیں کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ چرچے شروع ہوئے ہوں کہ نبیٔ مختون کی آمد کا وقت قریب ہے اور یہود و نصاریٰ کے علماء سے انہوں نے یہ سنا ہو کہ موعود نبی عرب میں ظاہر ہونے والا ہے تو اپنی قومی روایات کو ملا کر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ اگر یہ موعود نبی عرب میں آیا تو پھر مکہ میں ہی آئے گا اور اس طرح ان کےد ل میں یہ احساس پیدا ہوا ہو کہ جب ہمارے لئے خدا تعالیٰ یہ نعمت ظاہر کرنے والا ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی قوم کو وہاں لے جا کر بٹھا دیں.تاکہ جب نبیٔ عرب کے ظہور کا وقت آئے تو ہماری قوم اس پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی برکات حاصل کرے.جیسا کہ مدینہ والوں نے کیا کہ انہوں نے یہودیوں سے آنے والے نبی کے متعلق باتیں سنیں اور انہی باتوں کے نتیجہ میں وہ
Page 431
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے.چنانچہ تاریخ میں مذکور ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور آپ کی قوم نے آپ کی مخالفت شروع کی تو ایک دفعہ مدینہ سے چند افراد حج کے لئے مکہ میں آئے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ میں تمہیں خدا کا یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ تم شرک کو چھوڑ دو.خدائے واحد کی پرستش کرو اور اخلاقِ فاضلہ اپنے اندر پیدا کرو.جب آپ یہ باتیں کہتے تو باہر سے آئے ہوئے لوگ قہقہ مار کر اور ایک دوسرے کی طرف آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھتے اور یہ کہتے ہوئے کہ معلوم ہوتاہے ’’یہ وہی مکہ کا پاگل ہے‘‘ منہ پھیر کرچلے جاتے (تفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ).روحانی نقطۂ نگاہ کو مدّ ِنظر رکھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دنیا کی نجات کے لئے آپ پاگل ہو رہے تھے.آپ کےد ل میں درد تھا کہ کسی طرح یہ دنیا ہلاکت اور تباہی کے راستوں سے بچ جائے.ان معنوں کے لحاظ سے اگر کوئی شخص آپ کو پاگل کہتا ہے تو ہم اسے کہیں گے خدا کرے ایسے پاگل دنیا میں اور بھی پیدا ہوں کیونکہ ان معنوں کا پاگل بڑی قیمتی چیز ہے.لیکن وہ لوگ جو کچھ کہتے مخالفت اور عناد کے نتیجہ میں کہتے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے انکار کر دیتے لیکن باوجود اس کے آپ مایوس نہ ہوتے اور حج کے دنوںمیں آپ ایک ایک قبیلہ کے پاس جاتے اور خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے.ایک سال مدینہ کے کچھ لوگ جو حج کے لئے آئے ہوئے تھے آپ نے ان کو تبلیغ شروع کی.ان کےدلوں میں کچھ شرافت تھی.کچھ یہودیوں سے بھی انہوں نےباتیں سنی ہوئی تھیں جب ایک جگہ کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی تو انہوں نے آپ سے کہا آئیےہم ایک طرف کنارے پر بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں.چنانچہ سب ایک طرف بیٹھ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام بدء اسلام الانصار).کچھ دیر سننے کے بعد انہوں نے کہا ہمارے شہر میں کچھ یہودی بستے ہیں اور چونکہ ہم زیادہ ہیں اور وہ تھوڑے ہیں اور معاہدات میں ہمارا پہلو غالب رہتا ہے وہ ہمیشہ ہم سے کہا کرتے ہیں کہ آج کل اس ملک میں ایک بہت بڑا نبی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ذریعہ ہم لوگ تم پر غالب آجائیں گے لیکن اس نے ہم میں سے آنا ہےاور مدینہ میں آنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم مدینہ میں آبسے ہیں.جب وہ وقت آئے گا ہم اس کے ذریعہ سے پھر ترقی کریں گے.مگر ہمیں تو آپ کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کےمتعلق یہودی یہ سمجھتے تھےکہ ان میں سے آنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے آنا تھا.ہمیں آپ کی باتیں سچی نظر آتی ہیں اور جو علامتیں یہودیوں نے ہمیں بتائی تھیں وہ آپ میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں مگریہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم نے اس بارہ میں کوئی فیصلہ کیا تو قوم میں جوش پیدا نہ ہو جائے.اور وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ تو
Page 432
غلطی سے مان آئے ہیں اب ہمیں بھی غلطی میںمبتلا کرنا چاہتے ہیں.آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی قوم کے سامنے یہ باتیں رکھیں اور پھر اگر خدا انہیں اور ہمیں توفیق دے تو آپ پر ایمان لے آئیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے.چنانچہ وہ لوگ گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو یہ تمام باتیں بتائیں.چونکہ وہ لوگ آنے والے نبی کےمتعلق یہودیوں سے مختلف باتیں سنتے رہتے تھے.نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال مدینہ کے ۱۲ آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے.اس طرح اسلام مکہ سے مدینہ جا پہنچا(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام العقبۃ الاولٰی).میں سمجھتا ہوں اسی طرح بالکل ممکن ہے قصی بن حکیم نے بھی یہودی علماء اور نصاریٰ سے اس قسم کی باتیں سنی ہوئی ہوں اور ان کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ خدا تو ہمارے گھر میں نبوت کا چشمہ پھوڑنے والا ہے اور ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اور اسی بناء پر انہوں نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی ہو کہ آؤ اور مکہ میں اکٹھے ہو جاؤ تاکہ آنے والے ظہور سے فائدہ اٹھا سکو.میں نے اوپر کہا تھا کہ خدا کی انگلی نے انہیں اشارہ کیا اور وہ مکہ میں جمع ہو گئے.لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہود اور نصاریٰ سے آنے والے نبی کی باتیں سنیں اور جب انہیں معلوم ہو اکہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے تو اپنی قومی روایات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وعدے ملا کر انہوں نے یہ نتیجہ نکال لیا ہو کہ وہ نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے.بظاہر ان دونوں میں اختلاف نظر آتا ہے لیکن درحقیقت کوئی اختلاف نہیں.اس لئے کہ اگر انہوں نے یہود اور نصاریٰ سے سن کر ایسا کیا تب بھی یہو داور نصاریٰ نے جو کچھ بتایا وہ خدائی پیشگوئیاں تھیں اور خدائی پیشگوئیاں بھی قدرت کی انگلی ہوتی ہیں جو بنی نوع انسان کی راہنمائی کرتی ہیں.اور اگر انہوں نے ان پیشگوئیوں کو نہیں سنا تب بھی یہ خدا ئی انگلی اور اس کی قدرت کا ایک زبردست ہاتھ تھا کہ جس بات کا انہیں دو ہزار سال تک خیال نہ آیا وہ نبیٔ عرب کے ظہور سے سوا دو سو سال پہلے انہیں یاد آگئی اور ایسی یاد آئی کہ ہزاروں تکالیف کے باوجود وہ مکہ میں آکر بس گئے.پس اگر وہ یہود و نصاریٰ کی باتیں سن کر آئے تب بھی اور اگر وہ خود بخود آئے تب بھی، جو کچھ ہوا قدرت کے اشارہ کے ماتحت ہوا اور اس طرح اپنی قوم کو وہاں جمع کر کے وہ خدائی تدبیر کا آلۂ کار بن گئے.پھر ہاشم کے زمانہ میں شام اور یمن کی طرف تجارتی قافلے جاری کرنے کی سکیم بھی اسی الٰہی تدبیر کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے.یمن میں اس وقت مسیحیت پھیلنی شروع ہو گئی تھی اور شام میں تو مسیحیت غالب آچکی تھی.شام سے بھاگ کر یہودی شمالی عرب میں آگئے تھے.اسی طرح وہ یمن میں بھی چلے گئے تھے.چنانچہ میں اوپر بتا چکا ہوں کہ یمن کا ایک حمیری بادشاہ جس نے بیس ہزار عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی ہو گیا تھا یا
Page 433
یہودیوں کی طرف مائل تھا.یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ یہودی شام سے بھاگ کر یمن میں چلے گئے تھے اور یہی قومیں تھیں جنہوں نے آئندہ زمانہ میں اسلام سے ٹکر لینی تھی.چنانچہ پہلے یمن کا واقعہ ہوا یعنی ابرہہ وہاں سے آیا اور اس نے خانۂ کعبہ پر حملہ کیا.اس کے بعد جب اسلام پھیلا تو شام کے عیسائیوں نے اسلام سے مقابلہ شروع کر دیا.پس اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کے ماتحت یہود اور نصاریٰ کے حالات سے مکہ والوں کو باخبر رکھنے کے لئے یہ شتاء و صیف کے سفر تجویز کرا دیئے.روزی کمانا اور چیز ہے مگر اس غرض کے لئے دو خاص ملکوں کو چن لینا اور چیز ہے.ورنہ ہاشم بن عبد مناف ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تجارتیں کیا کرو.مگر ان کا ایسی سکیم بنانا جس سے مکہ والوں کا یمن اور شام سے تعلق پیدا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس سورۃ کو اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ کے بعد رکھنا صاف بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا لٰہی سکیم کے ماتحت ہوا.اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انہیں اس طریق پر کام کرنے کے نتیجہ میں روزی بھی مل جائے اور انہیں شام اور یمن کے حالات بھی معلوم ہوتے رہیں جن سے کسی زمانہ میں ان کی ٹکر ہونی تھی چنانچہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ان میں سے ایک کی ٹکر اسلام کی بعثت سے پہلے ہوئی اور ایک کی ٹکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوئی.دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یمن اور شام میں عیسائی رہتے تھے اور عیسائیوں سے بڑی کثرت کے ساتھ انہیں ایسی خبریں مل سکتی تھیں جن میں آنے والے موعود کی خبر دی گئی تھی.اسی طرح یہود بھی ان مقامات پر رہتے تھے اور ان سے بھی آنے والے ظہور کے متعلق بہت سی خبریں معلوم ہو سکتی تھیں.پس ان دونوں سفروں سے مکہ والوں کو یہودیوں اور مسیحیوں سے میل ملاپ کا موقعہ ملتا تھا اور پرانے وعدے اس اَن پڑھ قوم کے دلوں میں تازہ ہوتے رہتے تھے اور اس طرح ان کی توجہ زیادہ سے زیادہ خانۂ کعبہ سے تعلق رکھنے والے مامور کی طرف پھرتی تھی.یہ لازمی بات ہے کہ جن لوگوں کے کانوں میں متواتر اس قسم کی باتیں پڑتی رہیں ان پر ایک قسم کا رعب پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے.چنانچہ جب وہ یہود اور نصاریٰ سے متواتر اس قسم کی باتیں سنتے تو وہ بھی یہ سمجھنے لگ جاتے کہ اب ضرور کسی نے آنا ہے اور اس طرح ان کی باتوں سے ان کے دلوں پر ایک چوٹ لگتی.ان کے کفر پر ایک کاری ضرب لگتی اور ان کی بے دینی کی دیوار میں شگاف پڑ جاتا.وہ جوں جوں سفر کرتے آنے والے ظہور کے متعلق متواتر یہود اور نصاریٰ سے پیشگوئیاں سنتے اور پھر وہ ان پیشگوئیوں کو مکہ میں آکر بیان کرتے اس طرح ساری قوم میں ایک حرکت سی پیدا ہو گئی اور ان میں بھی ایک نبی کی آمد کا احساس شروع ہو گیا.دوسری طرف اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب شام اور یمن میں مکہ والے جاتے تو یہودی اور عیسائی بھی سمجھتے کہ ہمیں مکہ والوں کی طرف سے خطرہ
Page 434
ہے ان کے مقابلہ کے لئے ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کیونکہ پیشگوئیاں سب عرب کی طرف اشارہ کرتی ہیں.غرض شتاء و صیف کے ان سفروں میں ایک بہت بڑی غرض اللہ تعالیٰ نے یہ مخفی رکھی ہوئی تھی کہ مکہ کے لوگ یہود و نصاریٰ سے بار بار ملیں اور آنے والے نبی کے متعلق ان سے پیشگوئیاں سنتے رہیں تاکہ جب اس نبی کا ظہور ہو اس پر ایمان لانا ان کے لئے آسان ہو.چنانچہ میں بتا چکا ہوں کہ مدینہ کے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق محض یہود سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہی ملی.اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ۠ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ( البقرۃ:۹۰) یعنی آج یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں مگر پہلے یہی یہود عربوں کو بتایا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی آنے والا ہے جس کے ذریعہ ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح حاصل ہو گی.پس اس شمال و جنوب کے سفر کی وجہ سے مکہ کے اَن پڑھ لوگ یہود و نصاریٰ کے علماء سے ملتے اور ان کی آراء سے جو وہ آخری نبی کے بارہ میں رکھتے تھے واقف رہتے چنانچہ اس کا ثبوت اس امر سے بھی ملتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے حضرت ابوطالب جب اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے سفر پر لے گئے تو وہاں ایک پادری نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ اس بچے کی خاص نگرانی کرنا اس میں ایسی علامات پائی جاتی ہیں شاید یہ بہت بڑا انسان ثابت ہو(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام قصۃ بحیرٰی) اور شاید عرب کے بارہ میں جو الہامی کلام ہے وہ اسی کے ذریعہ سے پورا ہو.اسی قسم کی باتیں مکہ والے ان سفروں میں متواتر سنتے رہتے تھے اور انہیں باتوں کو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں ابتدائی دور چلانے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتا تھا.پس یہ دونوں سفر درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کے ماتحت تھے.ورنہ وہ قوم جس میں الہام نہیں پایا جاتا تھا، جس کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، جو متمدن علاقوں سے بہت دور رہنے والی تھی اس کے لئے یہ کتنی مشکل بات تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو سن کر آپ پر ایمان لے آتی.مگر ان سفروں کے نتیجہ میں جب وہ لوگ متواتر یہودیوں اور عیسائیوں سے اس قسم کی باتیں سنتے تو ان کا اپنا عقیدہ کمزور ہو جاتا اور وہ سمجھتے کہ شاید کچھ بات ہو اور شاید کوئی آنےوالا ہم میں آہی جائے.پس یہ دونوں سفر اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت کے ماتحت تھے.اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی حالت پرتعجب کرو کہ کس طرح یہ قوم جو مکہ میں آبسی تھی جو بھوکی مر جاتی تھی مگر مکہ سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی اب باقاعدہ جس طرح نماز فرض ہوتی ہے، سردی آتی ہے تو یمن کی طرف چل پڑتے ہیں گرمی آتی ہے تو شام کی طرف چل پڑتے ہیں.یہ سفروں کی محبت ان کےد لوں میں آخر کس نے پیدا کی ہے صرف ہم نے پیدا کی ہے.اگر یہ مکہ میں بیٹھے رہتے تو ان کو کچھ بھی پتہ نہ چلتا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
Page 435
کے متعلق کیا کیا پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں مگر اب ان کے دلوں میں ان سفروں کی ایسی محبت پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ نہایت باقاعدگی کے ساتھ گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے ہیں یمن میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے اس قسم کی باتیں سنتے ہیں کہ ایک نبی آنےوالا ہے اور شاید وہ عرب سے ہی پیدا ہو.شام میں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے سنتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے.اور شاید وہ عرب سے ہی پیدا ہو.اس طرح ان کے کانوں کو ہم نے ان پیشگوئیوں سے آشنا رکھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق تھیں تاکہ آپ کے دعویٰ کو سنتے ہی وہ یک دم انکار نہ کر دیں اور واقعہ میں مکہ والوں کو کلامِ الٰہی سے جتنا بُعد تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہ کتنا مشکل تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر آپ پر ایمان لا سکتے.یہ انہی پیشگوئیوں کے سننے کا نتیجہ تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تو مکہ میں سے ہی کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو گئے جو فوراً آپ پر ایمان لے آئے چنانچہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکہ میں نہیں تھے بلکہ مکہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے.واپس آکے تو چونکہ سخت گرمی کا موسم تھا ایک دوست کے ہاں دوپہر کے وقت کچھ سستانے کے لئے ٹھہرے وہ ابھی لیٹے نہیں تھے کہ ان کے دوست کی لونڈی سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ کہنے لگی.ہائے ہائے بیچارا اس کا دوست تو پاگل ہو گیا ہے.حضرت ابوبکرؓ نے ادھر ادھر دیکھا اور سمجھا کہ یہ الفاظ شاید میرے متعلق ہی کہے گئے ہیں.چنانچہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کون دوست؟ اس نے کہا تمہارا دوست محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) حضرت ابوبکرؓ نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ لونڈی کہنے لگی وہ کہتا ہے میرے ساتھ فرشتے باتیں کرتے ہیں.حضرت ابوبکرؓ اس وقت لیٹنے ہی لگے تھے کہ یہ بات سن کر آپ نے چادر سنبھالی اور دوست سے کہا میں اب جاتا ہوں.اس نے کہا ذرا ٹھہریں سخت گرمی کا وقت ہے آپ کو اس وقت جانے سے تکلیف ہو گی.انہوں نے کہا نہیں اب میں ٹھہر نہیں سکتا.چنانچہ وہ سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز سن کر تشریف لائے اور دروازہ کھولا.دروازہ کھلتے ہی حضرت ابوبکرؓ نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے فرشتے آپ پر نازل ہوتے ہیں اور وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال فرماتے ہوئے کہ یہ میرے دوست ہیں اور ان سے میرے پرانے تعلقات چلے آرہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھا جائیں مناسب سمجھا کہ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کچھ سمجھا لیں.چنانچہ آپ نے فرمایا ابوبکر پہلے میری بات سن لو بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکرؓ نے اسی وقت آپ کے سلسلہ کلام کو
Page 436
منقطع کرتے ہوئے کہا.میں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھتا آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے قبل پھر فرمایا.ابوبکر بات تو سن لو.آپ نے خیال فرمایا کہ اگر یک دم میں نے کچھ جواب دیا تو ممکن ہے یہ ٹھوکر کھا جائیں اس لئے تمہیداً میں ان سے چند باتیں کہہ لوں.مگر ابوبکرؓ نے کہا نہیں میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اور بات نہ بتائیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں؟ جب انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دی اور اصرار کیا کہ مجھے کوئی اور بات نہ بتائی جائے صرف میری بات کا جواب دیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور کوئی چارہ کار نہ رہا اور آپ نے فرمایا ابوبکر ٹھیک ہے میں نے کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں.اس بات کو سنتے ہی حضرت ابوبکرؓ نے کہا پھر آپ گواہ رہیں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور فرمایا یا رسول اللہ! آپ دلیلیں دے کر میرا ایمان خراب کرنا چاہتے تھے.میں نے آپ کے چال چلن اور طور طریق کو مدتوں سے دیکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کی صداقت کے متعلق میرے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں(شرح الزرقانی ذکر اول من اٰمن باللہ ورسولہٖ).پس میں کسی دلیل کی وجہ سے نہیں بلکہ خود آپ کی وجہ سےآپ پر ایمان لاتا ہوں.یہ کیا چیز تھی جس نے ابوبکرؓ کو یک دم ایمان لانے پر آمادہ کر دیا.یہ انہیں باتوں کا نتیجہ تھا جو مکہ والوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے متواتر سنی ہوئی تھیں ورنہ مکہ والے ان پیش گوئیوں کو کیا جانتے تھے اگر وہ شام اور یمن کے سفروں پر نہ جاتے، اگر وہ آنے والے نبی کے متعلق ان سے بار بار پیشگوئیاں نہ سنتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ٔ نبوت مکہ والوں کے لئے ایک ایسی غیر معمولی چیز تھی کہ شاید ابوبکرؓ جیسا انسان بھی آپ کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوتا مگر چونکہ متواتر ان کے کانوں میں یہ آوازیں پڑی ہوئی تھیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، دنیا میں ایسے مذاہب بھی ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیشگوئیاں کرتے ہیں اور پھر انہوں نے مخصوص طو رپر عرب کے متعلق یہود اور نصاریٰ سے یہ خبریں سنی ہوئی تھیں کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے اور ان باتوں سے ان کے کان پوری طرح آشنا تھے اس لئے ان باتوں نے ان کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا راستہ کھول دیا.پس مکہ والوں کے یمن اور شام کے سفر درحقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لئے بطور ارہاص تھے اور اس ذریعہ سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے تیار کئے جا رہے تھے.یہی وجہ ہے کہ سورۂ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ
Page 437
کے معاً بعد خدا تعالیٰ نے سورۃ ایلاف کو رکھا ہے.تفسیر.چونکہ بسم اللہ کے بعدکی دونوں آیتیں درحقیقت ایک مضمون پرمشتمل ہیں اس لئے ان دونوں کی تفسیر اکٹھی ہی کی جانی مناسب ہے.چنانچہ میں ان دونوں آیات کی تفسیر یکجائی طور پر بیان کرتا ہوں:.لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ.جو معانی میں اوپر بیان کر چکا ہوں ان کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ مختلف محذوفات کی وجہ سے جو لام سے پہلے نکالے گئے ہیں اور ایلاف کے مختلف معنوں کی وجہ سے اس آیت کے کئی معنے ہوں گے.جو قریباً ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے.پہلا مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم نے قریش کے دل میں سردی گرمی کے دونوں سفروں کی محبت پیدا کرنے کے لئے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا اور انہیں بھوسے کی طرح اڑا دیا.اس میں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس طرف اشارہ ہےکہ خدا تعالیٰ ان دونوں سفروں کو قائم رکھنا چاہتا تھا.ان معنوں کے رو سے خدا تعالیٰ کا زور دونوں سفروں کے قیام پر ہے.یعنی دونوں سفروں کا قیام الٰہی سکیموں کا ایک حصہ تھا.اور چونکہ الٰہی حکمت چاہتی تھی کہ یہ دونوں سفر قائم رہیں اس لئے اس نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا مگر میں بتا چکا ہوں کہ اس کے یہ معنے نہیں کہ’’اسی لئے‘‘ تباہ کیا بلکہ’’اس لئے‘‘ کے معنے ہیں.اور ’’اس لئے‘‘ اور ’’اسی لئے‘‘ میں فرق ہوتا ہے.’’اسی لئے‘‘ کے معنے ہوتے ہیں کہ یہی اصل مقصد تھا.مگر ’’اس لئے‘‘ کے معنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مختلف وجوہ میں سے یہ بھی ایک وجہ تھی.جیسا کہ میںپہلے بیان کر چکا ہوں اس تباہی کے کئی اسباب تھے.جن میں سے ایک یہ بھی تھا.پس یہاں ہم ’’اس لئے‘‘ کہیں گے نہ کہ ’’اسی لئے‘‘.میں نے بتایا ہےکہ ان کے سردی گرمی کے سفروں کے قیام کی بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگوئیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں تو محفوظ تھیں لیکن حضرت ابراہیمؑ کی پیشگوئیاں مکہ میں محفوظ نہیں تھیں.مکہ والے امتدادِ زمانہ کی وجہ سے ان پیشگوئیوں کا اکثر حصہ بھول چکے تھے.اس لئے ضروری تھا کہ ان کو وہ پیشگوئیاں دوسری قوموں کے ذریعہ سے یاد کروائی جائیں.یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرعی نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک دوسرے نبی کے تابع تھے.شریعت لانے والے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے.دوسرے ملکوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعتیں آئیں وہ الگ ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں.لیکن بنی اسرائیل کی نسل جن قوموں سےبراہ راست چلتی تھی ان میں حضرت نوح علیہ السلام شریعت لانے والے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شریعت کے تابع تھے.جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لانے والے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی شریعت کے تابع
Page 438
تھے.حضرت نوح علیہ السلام اپنے سلسلہ کے پہلے نبی تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سلسلہ کے آخری نبی تھے.جس طرح کہ بنی اسرائیل کے سلسلہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے.اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ(الصّٰفّٰت:۸۴) نوحؑ کی جماعت میں سے ابراہیمؑ تھے یعنی وہ علیحدہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ اسی سلسلہ کی ایک کڑی تھے.گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نوحی سلسلہ کے ایک نبی تھے اور چونکہ وہ نوحی سلسلہ کے ایک نبی تھے اس لئے کوئی علیحدہ شریعت نہیں لائے.چنانچہ بائبل پڑھ کر دیکھ لو صاف پتہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی شریعت نہیں تھی لیکن جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں شریعت کا بھی ذکر آجاتا ہے.پس حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شرعی نبی نہیں تھے ان کے زمانہ میں نوحؑ کی شریعت پر ہی عمل ہوتا تھا.اس کے بعد بنواسماعیل اور بنو اسحاق میں سے پہلے بنو اسحاقؑ میں نبوت آئی.باوجود اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور بنو اسماعیل میں بعد میں آئی.اس لئے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مقدّر تھا کہ وہ بنو اسماعیل میں سے آئیں گے.دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کےد ونوں بیٹوں کی نسلوں کے متعلق یہ وعدے تھے کہ ان میں نبی بھی آئیں گے اور بادشاہ بھی ہوں گے(پیدائش باب ۱۷آیت ۶ تا۲۰) اب اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ میں نبوت پہلے آجاتی تو بنو اسحاق کے متعلق جو الٰہی وعدے تھے وہ پورے نہ ہوسکتے کیونکہ خاتم النبییّن کے بعد تو کوئی نیا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا تھا اس لئے پہلے اسحاق کا سلسلہ جاری کیا گیا تاکہ جب یہ ختم ہو جائے توپھر اسمٰعیل کا سلسلہ شروع ہو کیونکہ اسمٰعیلی نبی نے خاتم النبیین کی صورت میں ظاہر ہونا تھا.بنواسحاق کے سلسلہ میں مختلف تاریخوں کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آٹھ سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں یا بعض لوگ چھ سو سال کا اندازہ بتاتے ہیں.یہ متفرق اندازے ہیں جن کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے چار سو سال سے آٹھ سو سال گذرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے.اب اگر ہم اس امر کو مدّ ِنظر رکھیں کہ حضرت عیسٰیؑ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ سو سال کا عرصہ گذرا ہے تو اسی پر قیاس کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی چھ سو سال کا فاصلہ ہو گا اور اسی پر قیاس کر کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام میں بھی چودہ سو سال کا فاصلہ ہو گا جس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں چودہ سو سال کا فاصلہ ہے.بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھ سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے.اس عرصہ میں نوحؑ کی شریعت تو
Page 439
جاری رہی مگر جب مٹتے مٹتے بالکل مٹ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ایک نئی شریعت بنی اسرائیل کے لئے آگئی.مگر ان کا موعود چونکہ خاتم النبیین تھا جس نے موسوی سلسلہ کے ختم ہونے پر آنا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو اسحاق میں تو شریعت کا دوبارہ اجراء ہو گیا اور وہ قوم اس سے غافل نہ ہوئی مگر بنو اسمٰعیل میں چونکہ شریعت نہ آئی اس لئے وہ کمزور ہوتے ہوتے ایسی حالت تک پہنچ گئے کہ ان میں سے شریعت بالکل مٹ گئی.وہ جنگلوں میں رہتے تھے غیرملکوں سے ان کے کوئی تعلقات نہ تھے.وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے اور کتابت کا فن بھی ان میں بالکل مفقود تھا اور اس بارہ میں اتنی کمزوری تھی کہ پڑھنے لکھنے والے عرب میں کوئی قابل قدر وجود نہیں سمجھتے جاتے تھے.سارے مکہ میں صرف سات آدمی تھے جو پڑھے لکھے تھے.گو اس بارہ میں روایتوں میں اختلاف ہے بعض پانچ کہتے ہیں، بعض سات کہتے ہیں، بعض گیارہ کہتے ہیں.مگر مکہ پندرہ بیس ہزار کا شہر تھا اس میں پانچ سات یا گیارہ کیا حیثیت رکھتے تھے.پھر جن کو پڑھنا آتا تھا ان کو بھی ان کی قوم نے پڑھنے کی اس لئے اجازت دی تھی تاکہ مختلف حکومتوں اور ریاستوں سے خط و کتابت کرنی پڑے تو ان سے کام لیا جا سکے یا معاہدات لکھنے ہوں تووہ لکھ سکیں گویا قومی ضرورت کے ماتحت ان کو جازت دی جاتی تھی کہ وہ پڑھ لیں.ورنہ یوں وہ یہی سمجھتے تھے کہ پڑھنا لکھنا کوئی اچھا کام نہیں اور اس کی وجہ ان کا یہ خیال تھا کہ پڑھنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اور یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے.پڑھنے کی وجہ سے حفظ کرنے کا شوق کم ہو جاتا ہے.دراصل عربوں میں علمِ ادب کا بڑا شوق تھا.اور گو وہ پڑھتے نہیںتھے مگر ہزاروں ہزار شعر حفظ کر لیا کرتے تھے.پس یہ تو ضرور فائدہ تھا مگر کم سے کم جو ضروری ریکارڈ محفوظ کرنا ہوتا تھا اسے بھی وہ تعلیم کے فقدان کی وجہ سے محفوظ نہیں کر سکتے تھے.نتیجہ یہ ہو اکہ نوحؑ کی تعلیم ان میں بالکل مفقود ہو گئی اور ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہیں آئندہ نبی کی بعثت کے متعلق ابراہیمی پیشگوئیوں اور اس کی تفصیلات کا علم نہ رہا.ان میں پیشگوئیاں تو تھیں مگر امتدادِ زمانہ اور پھر جہالت کی وجہ سے رفتہ رفتہ پیشگوئیوں کی تفصیل غائب ہو گئی.وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ ہمارے باپ ابراہیمؑ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہےاور اس لئے بٹھایا ہے کہ یہاں بیٹھنے سے ہماری ترقی وابستہ ہے جیسے ہمارے ملک میں ساہنسی یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ کسی زمانہ میں سارے ہندوستان میں تمہاری حکومت ہو جائے گی.مگر اس کے ساتھ کوئی علامتیں نہیں، کوئی آثارنہیں، کوئی تفاصیل نہیں جن سے یہ پتہ لگ سکے کہ یہ پیش گوئی کب پوری ہو گی اور اس کے پورا ہونے کی کیا کیا علامات ہوں گی.اسی طرح وہ اتنا تو جانتے تھے کہ ہمیں ہمارے باپ ابراہیم نے یہاں ہماری ترقی کے لئے بٹھایا ہوا ہے مگر نوحؑ اور ابراہیمؑ کی پیشگوئیاں وہ بالکل نہیں جانتے تھے.یہ تفصیلات یہود اور عیسائیوں میں موجود تھیں.اس لئے اللہ تعالیٰ
Page 440
نے یہ دیکھ کر کہ یہ جاہل بھی ہیں اور ان میں نوحؑ اور ابراہیمؑ کی تعلیم کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا یہو داور نصاریٰ سے ان کا تعلق قائم کرنے کے لئے یہ تدبیر کی کہ ہاشم بن عبد مناف کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ وہ ہر سال مکہ والوں کے قافلے یمن اور شام میں روانہ کیا کریں تاکہ تجارتی اموال کے ذریعہ ان کی حالت بھی درست ہو جائے اور یہود و نصاریٰ سے تعلقات پیدا ہو جانے کی وجہ سے محمدی پیشگوئیاں بھی ان کے سامنے بار بار آتی رہیں.دوسرے معنے اس کے یہ بنیں گے کہ اس امر پر تعجب کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قریش کو سردی گرمی کے سفر پر تیار کر دیا یعنی ان لوگوں کے دلوں میں سفر کی محبت پیدا کر دی.ان معنوں کے رو سے ایک دوسرے معنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بے شک ان معنوں سے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو سردی گرمی کے سفر پر تیار کر دیا اور اس طرح یہ محمدی دین کی طرف مائل ہو گئے.مگر ایک اور حکمت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور وہ یہ کہ ہاشم نے کہا تھا کہ اگر تم سفروں کے لئے نہ نکلے تو تم بھوکے مرو گے اور دوسری قوموں میں ذلیل ہو جاؤ گے.اللہ تعالیٰ اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سردی گرمی کے سفرکی دراصل ہم نے تدبیر کی تھی اگر یہ سفر نہ ہوتا تو ان میں ایمان تو تھا ہی نہیں صرف قومی رسم و رواج کی وجہ سے وہ وہاں ٹھہرئے ہوئے تھے.ممکن تھا کہ اگر وہ اسی طرح ایک لمبے عرصہ تک بھوکے مرتے چلے جاتے تو تنگ آکر وہ مکہ چھوڑ دیتے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں مکہ میں رکھنے کے لئے یہ تدبیر سُجھا دی ورنہ دنیا کی تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہزارہا قومیں دنیا میں ایسی گذری ہیں جنہوں نے اپنی معاشی ضرورتوں کے لئے جگہیں بدلی ہیں.یہی ایرنیز جو آج ہندوستان کے مالک بنے پھرتے ہیں تبت وغیرہ علاقوں اور چین کی طرف سے آئے تھے(تمدن ہند صفحہ ۲۴۰) اور پھر یہاں آکر بس گئے ان کا کچھ حصہ اپنے مرکز سے نکلا تو یورپ میں جا کر بس گیا.پھر مغلیہ قوموں کو ہی دیکھ لو ان میں سے کچھ ترکیہ میں جابسے کچھ فن لینڈ میں جابسے.اسی طرح ہنگری بھی مغلوں اور ترکوں سے بسا ہوا ہے.چین کے اوپر کے علاقوں اور منگولیا وغیرہ میں بھی مغل پائے جاتے ہیں.بلکہ بعض کے نزدیک تو مغلوں کی ابتداء ہی منگولیا سے ہوئی ہے(اردو دائرہ معارف اسلامیہ زیر لفظ مغل).پھر کچھ ہندوستان میں بھی آگئے.یہی حال پٹھانوں کا ہے.ہندوستان میں جن کو خان صاحب، خان صاحب کہہ کر پکارا جاتاہے یہ دراصل روٹی کی تنگی کی وجہ سے ہی افغانستان سے آئے تھے.کچھ معاشی حالت درست کرنے کے لئے اور کچھ معاشی مصیبتوں سے بچنے کے لئے.اسی طرح اور ہزاروں قومیں ہیں جو اپنے ملکوں سے نکلیں اور معاشی ضروریات کے لئے دوسرے ملکوں میں جا بسیں.عرب لوگ بھی اگر یہ سفر نہ کرتے تو بالکل ممکن تھا کہ معاشی ضروریات انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیتیں کہ وہ مکہ چھوڑ دیتے.
Page 441
بے شک ایک دفعہ قصی بن کلاب نے انہیں وہاں لا کر بسا دیا تھا مگر جن مشکلات کی وجہ سے انہوں نے پہلے مکہ چھوڑا تھا انہی مشکلات کی وجہ سے وہ دوبارہ بھی چھوڑ سکتے تھے.جب خدا پر انہیں یقین نہ تھا، جب اس کے نشانات ان کے سامنے نہ تھے، جب خدا کو وہ جانتے ہی نہیں تھے بلکہ دن رات بتوں کی پوجا کرتے رہتے تھے تو آخر یہ الٰہی تصرّف نہیں تھا تو اور کیا تھا کہ باوجود مخالف حالات کے اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ میں سے نکلنے نہیں دیا اور آخر ان کے گذارہ کے لئے یہ صورت پیدا کر دی کہ ان کے دل میں تجارتی سفروں کی تحریک پیدا کر دی گئی.چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ باہر کمانے کے لئے چلے جاتے اور باقی سب مکہ میں ہی بیٹھے رہتے، وہ کما کر لاتے اور دوسرے لوگ کھاتے.نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصہ میں ہی ان کی حالت دوسروں سے اچھی ہو گئی.یہ سفر بھی کوئی زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا.دو تین مہینہ کا سفر ہوتا تھا.اس کے بعد پھر مکہ میں آکر رہنا شروع کر دیتے تھے.پھر یہ بھی نہیں تھا کہ سارا مکہ سفر پر چلا جاتا تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ قافلہ میں صرف دو تین سو آدمی شامل ہو اکرتے تھے حالانکہ مکہ کی آبادی پندرہ بیس ہزار تھی.اگر جوان مردوں کا اندازہ لگایا جائے تو پندرہ بیس ہزار کی آبادی میں تین چار ہزار جوان ضرور ہو گا اور اگر بوڑھے اور کہولت کے زمانہ والے بھی ملا لئے جائیں تو پانچ چھ ہزار آدمی بن جاتا ہے.ان میں سے صرف دو تین سو شام چلا جاتا دو تین سو آدمی یمن چلا جاتا اور باقی سب وہیں رہتے.یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے کا سارا مکہ خالی ہو جاتا اور سب یمن یا شام کی طرف چل پڑتے.صرف دو تین سو آدمی قافلہ میں جایا کرتے تھے (تـفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ) اور جو باقی رہتے وہ ان لوگوں کی جو عمرہ وغیرہ کے لئے آیا کرتے تھے خدمت کرتے اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا خیال رکھتے اور اس کا خود حدیثوں میں سے بھی ثبوت ملتا ہے.حدیثوں میں صاف ذکر آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے سفر نہیں کرتے تھے.چنانچہ مکہ کے امراء کی نسبت احادیث میں آتا ہے اِنَّـھُمْ کَانُوْا یَشْتُوْنَ بِـمَکَّۃَ وَ یَصِیْفُوْنَ بِالطَّائِفِ (سراج منیر سورۃ قریش ) یہ ابن عباسؓ سے روایت ہے اور اس کے معنے یہ ہیں کہ امراء مکہ سردی کے موسم میں مکہ میں رہتے تھے اور گرمیاں طائف میں گذارتے تھے کیونکہ طائف پہاڑی علاقہ ہے اور اس میں سردی ہوتی ہے پس یہ سفر صرف چند آدمی کرتے تھے سارے کے سارے اس سفر پر نہیں نکلتے تھے مگر اس قافلہ کی وجہ سے گذارہ سب کو مل جاتا اور وہ خانۂ کعبہ کی خدمت میں مشغول رہتے.مجھے یاد ہے حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ کے وقت میں جب میر محمد اسحاق صاحب کی تعلیم کا زمانہ آیا.(میر صاحب مجھ سے پونے دو سال چھوٹے تھے) تو ہمارے نانا جان مرحوم نے حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا کہ اسے کیا پڑھایا جائے.آپ نے فرمایا اس کو دینی تعلیم دلوائیے.ایک بیٹے کو تو آپ نے دنیا پڑھائی ہے
Page 442
اس کو دینی تعلیم دلوا دیں.اس پر نانا جان مرحوم نے اپنی طرف سے یا نانی امّاں کی طرف سے کہا کہ پھر تو یہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پلے گا.جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا بعض دفعہ ایک شخص کو دوسرے کی خاطر روٹی دیتا ہے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر یہ دینی خدمت میں مشغول رہا تو اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پلے گا.آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ دین کی خدمت کرے گا تو اس کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کی روزی میں بھی برکت پیدا کر دے گا.پھر آپ نے حضرت ابوہریرہؓ کا واقعہ سنایا.جب وہ اسلام لائے تو ان کے دل میں شوق پیدا ہو اکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھوں اور آپ کی باتیں سنوں.چنانچہ وہ رات دن مسجد میں بیٹھے رہتے تھے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی باہر تشریف لائیں اور کوئی بات کریں تو اس کے سننے سے محروم نہ رہیں.ان کی روایات کی کثرت کو دیکھ کر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہؓ بڑے پرانے صحابی تھے حالانکہ وہ پرانے صحابی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ت سے صرف تین سال پہلے ایمان لائے تھے(اسد الغابۃ، ابوھریرۃ) مگر روایتیں سب سے زیادہ انہی کی ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ پرانے پرانے صحابیوں کو نہیں جانتے مگر ابوہریرہؓ کو جانتے ہیں.کیونکہ حدیثوں میں بار بار آتا ہے کہ ابوہریرہؓ نے یہ کہا ابوہریرہ نے وہ کہا.غرض وہ بہت بعد میں اسلام لائے ہیں لیکن ان کے دل میں دین سیکھنے کا جوش تھا جب وہ ایمان لائے تو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے متعلق انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ چونکہ اور لوگوں نے آپ کی بہت سی باتیں سن لی ہیں اور مجھے آخر میں ایمان لانے کی توفیق ملی ہے اس لئے میں اب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا.چنانچہ جس طرح قریش مکہ میں آکر بیٹھ گئے تھے وہ بھی مسجد میں آکر بیٹھ گئے اور انہوں نے عہد کیا کہ جس طرح بھی ہو سکا میں دین کی خدمت کروں گا دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا.ان کا ایک بھائی بھی مسلمان ہوچکا تھا.چونکہ یہ سب کاروبارچھوڑ کر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آبیٹھے تھے اس لئے کچھ مدت تک تو وہ اپنے ایمان کے جوش میں اپنے بھائی کو کھانا پہنچاتا رہا.عربوں کی زندگی بہت ہی سادہ ہوا کرتی تھی وہ کھجوریں کھا کر پانی پی لیتے اور اس کو غذا کے لئے کافی سمجھتے یا کبھی سوکھا گوشت مل جاتا تو وہی کھا کر پانی پی لیتے(ابن ماجہ کتاب الاطعمہ باب القدید).غرض بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور ان کو کھانا پہنچانا کوئی مشکل امر نہ تھا.مگر کچھ مدت تک ایمان کے جوش میں انہیں کھانا پہنچانے کے بعد حضرت ابوہریرہؓ کا بھائی تنگ آگیا.(حضرت ابوہریرہؓ ایک عیسائی خاندان میں سے تھے اور ان کی والدہ بھی عیسائی تھیں) جب اس نے تنگی محسوس کی تو ایک دن وہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ابوہریرہؓسے کہیے کہ وہ
Page 443
کچھ کمایا بھی کرے.یہ کیا کہ سارا دن مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے کوئی کام نہیں کرتا.رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ خدا اس کے طفیل تمہیں بھی رزق دیتا ہو.حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ نے یہی واقعہ ہمارے نانا جان مرحوم کو سنایا چنانچہ اس کے بعد نانا جان مرحوم نے دنیوی تعلیم کا ارادہ چھوڑ کر انہیں اسی کام پر لگا دیا.غرض کچھ لوگ مکہ والوں میں سے سفروں پر جاتے تھے اور کمائی کر کے لاتے تھے اور باقی لوگ مکہ میں ہی رہتے.مکہ میں رہنے والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قافلہ والوں کے کام میں بھی برکت پیدا کر دیتا اور اس طرح ان کا بھی گذارہ ہو جاتا اور مکہ والے بھی پلتے رہتے.بہرحال مکہ والوں کا اکثر حصہ وہیں مکہ میں رہتا تھا صرف ایک حصہ تجارت کرتا اور وہ جو کچھ کما کر لاتا وہ مکہ والوں میں بانٹ دیتا.یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں دنیا میں اس کی کتنی مثالیں پائی جاتی ہیں.اگر یہ محض ایک انسانی تدبیر تھی تو دیکھنا یہ چاہیے کہ دنیا میں اور کہاں کہاں اس طریق پر عمل ہوتا ہے یقیناً دنیا کی اور کسی قوم نے وہ مثال قائم نہیں کی جو مکہ کے یہ لوگ قائم کر چکے ہیں.ہماری جماعت کو ہی دیکھ لو جب وقف کی تحریک کی جاتی ہے تو ان میں سے کتنے نکلتے ہیں.دعویٰ یہ ہے کہ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ(الجمعۃ:۴) والی جماعت ہم ہی ہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی جماعت ہیں مگر ان میں سے کتنے دین کے لئے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں.دوسروں کے کام کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے اور چیز ہے اور حقیقت کو مدّ ِنظر رکھنا اور بات ہے.کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مکہ والوں نے جو کچھ کیا وہ ایک معمولی بات ہے مگر سوال یہ ہے کہ آج بھی اس مثال پر کتنے لوگ عمل کر سکتے ہیں یا کتنے لوگ عمل کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں.کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا تو لوگوں نے حسد کی وجہ سے اس کے اس فعل کی تحقیر شروع کر دی.چنانچہ وہ جہاں بھی بیٹھتا لوگ اس پر طنز کرتے کہ کولمبس نے بڑی دریافت کی ہے.وہ جہازمیں بیٹھا اور سامنے ایک ملک آگیا.بھلا اس دریافت میں اس نے کیا کیا ہے.ایک دفعہ کسی دعوت میں بہت سے لوگ شامل تھے اور مذاقیہ رنگ میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ کولمبس نے اپنی جیب میں سے ایک انڈا نکالا اور کہا اسے میز پر کھڑا کر دیں.جن لوگوں نے یہ کوشش کی وہ ناکام رہے.جب وہ سارا زور لگا چکے اور انڈا کھڑا نہ ہوا تو کولمبس نے جیب میں سے ایک بڑا سا سؤا نکالا اور انڈے میں سوراخ کر دیا.سوراخ کی وجہ سے اس میں سے لعاب نکل آیا.کولمبس نے اس لعاب کے ذریعہ سے انڈے کو میز پر کھڑا کر دیا.اس پر کولمبس نے کہا دیکھا انڈا کھڑا ہو گیا یا نہیں.تم کہتے تھے کہ امریکہ کا سفر کولمبس نے کیا اور امریکہ دریافت ہو گیا ہمیں یہ موقعہ نہ ملا اس لئے ہم رہ گئے.مگر اس انڈے کو کھڑا کرنے کا تو تم کو موقعہ مل گیا تھا تم اسے کھڑا نہ کر سکے(Admiaral of the Ocean Sea vol:1 P:349).تو حقیقت یہ ہے کہ کام
Page 444
کرنا اور چیز ہے اور یہ کہہ دینا کہ ایسا کام تو ہر شخص کر سکتا ہے اور بات ہے.اگر یہ ایسی ہی آسان بات ہے تو دنیا میں اور کسی نے وہ کیوں نہ کر لیا جو مکہ والوں نے کیا تھا.کیا دنیا کے پردہ پر آج کوئی شہر، کوئی قصبہ اور کوئی بستی ایسی ہے جس میں یہ طریق رائج ہو کہ چند لوگ روزی کما کر لاتے ہوں اور پھر شہر والوں کو کھلا دیتے ہوں اور ان سے کہتے ہوں کہ تم اطمینان سے یہاں بیٹھے رہو ہم کمائیں گے اور تمہیں کھلائیں گے ہم نے تو دیکھا ہے احمدیوں میں سے بھی بعض ایسے بے حیا اور بے شرم ہو تے ہیں کہ وہ بڑی ڈھٹائی سے کہہ دیتے ہیں کہ مبلّغوں کا کیا ہے وہ تو پیسے لے کر کام کرتے ہیں.ان بے حیاؤں سے کوئی پوچھے کہ تم بغیر پیسے کے کام نہ کرو وہ پیسے لے کر کام نہ کریں تو دین کا کام کون کرے پھر تو دین کا خانہ ہی خالی ہو جائے.حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح تم کما سکتے تھے اسی طرح وہ بھی کما سکتے تھے یہ کہنا کہ غربت کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے یا دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے تھے بالکل جاہلانہ بات ہے.ڈاکٹر اقبال کے باپ بہت ہی معمولی آدمی تھے.ٹوپیاں بنایا کرتے تھے مگر ان کا ایک بیٹا انجینئر ہو گیا اور دوسرا علّامہ کہلانے لگا.اسی طرح سید احمد صاحب کیا تھے؟ ایک بہت ہی غریب آدمی کے لڑکے تھے مگر ترقی کر کے کہیں کے کہیں جا پہنچے(حیات جاوید صفحہ ۹۵).پس یہ کہنا کہ وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے تھے اس لئے دین کی طرف چلے گئے بالکل غلط ہے.دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ بڑے بڑے غریب لوگوں کی اولادیں بڑے بڑے اعلیٰ مقام تک جاپہنچیں.پھر سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دین میں اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے تو اسی طرح وہ دنیوی کاموں میں بھی اپنی قابلیت ظاہر کر سکتا تھا مگر اس نے یہی چاہا کہ وہ خدا کا کام کرے اور دنیا کے کام کو نظرانداز کر دے.اصل بات یہ ہے کہ محض اس حسد اور غصہ کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں یہ کیوں طعن کرتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت نہیں کرتے.بعض لوگ اس قسم کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ مبلّغوں کا کیا ہے وہ بھی تو نوکری کرتے ہیں حالانکہ یہ انتہا درجہ کی بے شرمی کی بات ہے.پس یہ کہنا کہ مکہ والوں نے اگر ایسا کیا تو اپنی حالت کو درست کرنے کے لئے کیا اس میں قربانی کی کون سی بات ہے محض واقعات پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے اگر ایسا ہر شخص کر سکتاہے تو سوال یہ ہے کہ باقی قومیں ایسا کیوں نہیں کر لیتیں اور وہ کیوں خاموش ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس خوبی کو مکہ والوں کی طرف منسوب کریں تو اس کے معنے یہ بنتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ نیک جماعت تھی کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، باجود اس کے کہ وہ بے دین تھے انہوں نے وہ کچھ کیا جو کئی مسلمانوں نے نہیں کیا.انہوں نے وہ کچھ کیا جو کئی احمدیوں نے بھی نہیں کیا.اس رنگ کی قربانی میں احمدی یقیناً مکہ والوں کے برابر نہیں ہیں بلکہ اس قربانی میں صحابہؓ بھی مکہ والوں کے برابر نہیں.اور اگر اس قربانی میں وہ صحابہ
Page 445
سے بھی بڑھے ہوئے تھے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے والوں سے بھی بڑھے ہوئے تھے تو ہم سوائےاس کے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ایک نشان تھا جو خدا نے د کھایا.ایک آسمانی تدبیر تھی جس کو خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا.مکہ والوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ایسا کر سکتے.یہ خدا کا نشان تھا اور اسی خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث کرنا چاہتا تھا اور یہی بات خدا تعالیٰ اس جگہ کہہ رہا ہے کہ مکہ والوں نے باوجود اس کے کہ وہ بے دین تھے، باوجود اس کے کہ وہ مشرک تھے، باوجود اس کے کہ وہ روحانیت سے عاری تھے، وہ فعل کیا جو آج تک دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکی.پس وہ فعل مکہ والوں نے نہیں کیا وہ فعل ہم نے ان سے کروایا.وہ صرف ہمارے تصرّف اور اثر کا نتیجہ تھا.انہوں نے جو کچھ کیا ہم اس کی وجہ قومی کیریکٹر قرار نہیں دے سکتے کیونکہ قومی کیریکٹر کے ہوتے ہوئے بھی بھوک پیاس کی تکلیف پر لوگ ادھر ادھر بھاگ جایا کرتے ہیں.اسے ہم صرف خدا تعالیٰ کا تصرّف اور خدا تعالیٰ کی تدبیر ہی کہہ سکتے ہیں.مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ چونکہ مکہ والوں کا کام ان کا اپنا کام نہ تھا خدا تعالیٰ کا کام تھا.اس لئے ہم اس کی نقل اتارنے کی کوشش نہ کریں.جس حد تک اس قربانی کی مثال ہم پیش کر سکیں ہمیں پیش کرنی چاہیے جب تک ہم ایسا نہ کریں ہم دنیا میں کوئی بڑا انقلاب پیدا نہیں کر سکیں گے.صحابہؓ نے بے شک دنیا میں انقلاب پیدا کیا لیکن وہ انقلاب ایسی ہی قربانی کی مثال قائم کرنے کی کوشش سے پیدا کیا.اگر وہ بالکل اس معیار پر پورے اترتے تو جو مکہ والوں میں معجزہ کے طور پر اور ظہور محمدؐی کے پیش خیمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا.تو یقیناً صحابہؓ اپنی ترقی کے معیار کو اور بھی اونچا لے جاتے.وہ اسلام کی بنیادوں کو اور بھی مضبوط کر دیتے.وہ کفر کی تباہی کو اور بھی مکمل کر دیتے ہماری جماعت کے افراد کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اس وقت کیا نمونہ پیش کر رہے ہیں.جب وہ غیروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہماری جماعت کتنی قربانی کر رہی ہے.کس طرح نوجوان اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں کیونکہ وہاں غیر کی طرف سے انہیں عزت مل رہی ہوتی ہے.مگر جب اندر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ان مولویوں کا کیا ہے یہ تو پیسے لے کر کام کرتے ہیں.حالانکہ جو کچھ مکہ والوں نے کیا اگر ساری جماعت قربانی کے اس نقطہ تک پہنچ جائے تو دنیا میں حیرت انگیز طو رپر ہماری تبلیغ کا سلسلہ وسیع ہو جائے.میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کی ماہوار آمد پچیس تیس لاکھ سے کم نہیں.اگر دین کو دنیا پر مقدّم کیا جائے جس کے معنے کم از کم ۵۱ فی صدی کے ہیں تو تیرہ لاکھ ماہوار آمد بن جاتی ہے.میں نے جماعت کی آمد کا جو یہ اندازہ لگایا ہے یہ غلط نہیں.حفاظتِ قادیان کے لئے جو تحریک کی گئی تھی اس میں ماہوار آمدن کے ساڑھے تیرہ لاکھ کے وعدے تھے اور ابھی جماعت کا بہت سا حصہ باقی تھا جس نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا تھا.
Page 446
پھر جماعت کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جو اپنی آمدن صحیح نہیں بتاتا.مجھے معلوم ہے ایک شخص کی جائیداد مجھ سے زیادہ تھی مگر میرے چندہ سے اس کا چندہ بہت کم تھا.شاید اس میں اندازہ کی غلطی تھی یا اس کی وجہ کمزوریٔ ایمان تھی.بہرحال اس کو دیکھتے ہوئے میرا اندازہ یہی تھا کہ ہماری جماعت کی ماہوار آمدن ۲۵.۳۰ لاکھ سے کم نہیں.اگر ۵۱ فی صدی چندہ دیا جائے اور ۲۵ لاکھ ماہوار آمد اوسطاً سمجھ لی جائے تو ۲ ۱ ۱۲ لاکھ ماہوار آمد ۵۰ فی صدی کے حساب سے اور تیرہ لاکھ ۵۱ فی صدی کے حساب سے بن جاتی ہے.مکہ والے بھی آخر اپنی آمد کا نصف قومی کاموں کے لئے دے دیا کرتے تھے.وہ کافر تھے، وہ بے ایمان تھے، وہ مشرک تھے مگر وہ سب کے سب اپنی آمد کا نصف اس لئے نکال دیا کرتے تھے تاکہ وہ غربا میں تقسیم کیا جائے اور مکہ آباد رہے.ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا ان کے پاس قرآن نہیں تھا، ان کے سامنے قومی ترقی کا کوئی مقصود نہیں تھا، ان کے سامنے کوئی اعلیٰ درجے کا آئیڈیل نہیں تھا.محض اتنی بات تھی کہ قصیّ نے ہم کو کہا ہے کہ ہمارے دادا ابراہیمؑ نے یہ کہا ہے کہ مکہ میں رہو.اس لئے ہم یہاں رہنے کے لئے آگئے ہیں.یہ کتنا چھوٹا سا آئیڈیل ہے.اس کے مقابلہ میں تمہارا آئیڈیل کیا ہے.تمہارا آئیڈیل یہ ہے کہ تم نے دنیا فتح کرنی ہے تم نے دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت قائم کرنی ہے تم نے دنیا میں خدا کی بادشاہت قائم کرنی ہے.وہ اپنے چھوٹے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اپنا نصف مال لا کر دے دیتے تھے.ان میں سے ہر شخص اپنی آمد کا آدھا حصہ نکال کر کہتا کہ یہ آدھا حصہ غریبوں کے لئے ہے تاکہ مکہ آباد رہے اور وہ اسے چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جائیں.مگر تم بڑے مقصد کے لئے وہ قربانی نہیں پیش کر سکتے اگر تم ایسا کرو تو سلسلہ کی سالانہ آمد سوا کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ ہونی چاہیے.اگر جماعت مکہ والوں کی قربانی کے برابر قربانی کرنے لگ جائے، اس سے نصف بھی کرنے لگ جائے، اس سے چوتھا حصہ بھی کرنے لگ جائے تو کتنا عظیم الشان کام ہو سکتا ہے.کتنی تبلیغ وسیع ہو سکتی ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ مدینہ میں آگئے صحابہؓ نے بڑی بڑی قربانیاں کیں مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان بحیثیت قوم قربانی کے اس معیار کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے.حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں فتنہ پیدا ہوا.مان لو کہ یہ کسی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوا مگر اتنا تو ہے کہ اس وقت لوگوں کی طبائع میں جوش پیدا ہو گیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ قومی تباہی ہمارے سامنے کھڑی ہے انہوں نے اگر دیکھا تو اس بات کو کہ ہم حق پر ہیں.اس وقت بعض صحابی بھی آپ کے مقابلہ میں تھے.چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں مگر بہرحال وہ کہلاتے تو صحابہ ہی تھے.پھر حضرت علیؓ کا زمانہ آیا اس زمانہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ
Page 447
کتنے ہی چھوٹے تھے بہرحال علیؓ کے مقابلہ میں صحابہ کہلانے والے موجود تھے.ہم مان لیتے ہیں کہ علیؓ بالکل غلطی پر تھے، ہم مان لیتے ہیں کہ علیؓ ہرگز خلافت کے مستحق نہیں تھے.مگر سوال یہ ہے کہ علیؓ کے پاس خلافت آنے سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا مگر علیؓ کو ضعف پہنچ جانے سے اسلام کو ضعف پہنچ سکتا تھا.لیکن وہ اتنی موٹی بات کو بھی نہ سمجھ سکے اور انہوں نے لڑائیاں شروع کر دیں.دو خلافتوں میں آدھی دنیا فتح ہو چکی تھی اگر باقی دو خلافتیں اسی اطمینان کے ساتھ چلنے دیتے تو باقی ساری دنیا پر بھی اسلام پھیل جاتا اور پھر نہ تباہیاں ہوتیں نہ بربادیاں ہوتیں نہ خرابیاں پیدا ہوتیں.مگر وہ اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھ سکے اور ان کے دلوں میں یہی بات رہی کہ ہم حق پر ہیں ہم اپنا حق چھوڑ نہیں سکتے.حالانکہ انہی لوگوں میں وہ صحابی بھی تھے جنہوں نے فتنہ کے خیال سے کبھی اپنے حق کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا.حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں میں اپنی کمر کو پٹکا باندھے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ معاویہ آئے اور انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر ایک تقریر کی جس میں کہا میں نے سوچا ہے میرے بعد حکومت کے لئے میرا لڑکا یزید سب سے زیادہ موزوں ہے اس میں وہ تمام قابلیتیں موجود ہیں جو حکمران میں ہونی چاہئیں.اس لئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہو گا.کوئی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ اس منصب کا یزید سے زیادہ حقدار ہے.حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں میں نے پٹکا کھولا اور میں نے کھڑے ہو کر یہ کہنا چاہا کہ سب سے زیادہ اس منصب کا وہ حقدار ہے جس کا باپ اس وقت اسلام کے لئے لڑ رہا تھا جب تیرا باپ کافر تھا اور جو اس وقت اسلام کے لئے خود لڑ رہا تھا جب تو کافر تھا مگر پھر خیال آیا کہ اگر میں نے یہ کہہ بھی دیا تو اس کا فائدہ کیا ہو گا اسلام میں پہلے ہی تفرقہ کم نہیں اس سے اور بھی بڑھ جائے گا اوریہ جائز نہیں کہ میں ایک دنیوی بات کی خاطر اسلام کی ترقی اور اس کے مفاد کو نقصان پہنچاؤں(بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الخندق و ھی الاحزاب).یہ حقیقی قربانی تھی.اگر مسلمان سارے کے سارے چھوٹے اور بڑے اس نقطۂ نگاہ کو سمجھ لیتے تو یقیناً اسلام میں وہ تفرقہ پیدا نہ ہوتا جس نے اس کی بنیادیں ہلا دیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت سی باتوں میں حق پر تھے مگر سوال یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر انسان کو اپنا حق بھی قربان کرنا پڑتا ہے.جب زیادہ بڑا مقصد سامنے آجائے تو اس وقت قربانی اور صرف قربانی ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے کام آتی ہے.اگر اس وقت کے مسلمان بھی ایسا کرتے اور وہ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح نہ دیتے تو یقیناً اسلام کی ترقی کہیں سے کہیں نکل جاتی.مگر افسوس کہ آخری دو خلفاء کے وقت میں بعض مسلمانوں سے وہ قربانی پیش نہ کی جا سکی جو مکہ والوں نے پیش کی تھی اور جس کا نتیجہ ظہور محمدؐی تھا.خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کی تاریخوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ صدیوں تک ایک قوم کے افراد اپنے لئے
Page 448
تمام ترقی کے راستوں کو روک کر اس گھر کو آباد رکھنے کے لئے جسے وہ خدا کا گھر سمجھتے ہیں کمائیں آپ اور کھلائیں دوسروں کو.انفرادی مثالیں تو مل جاتی ہیں مگر قومی طو رپر اور متواتر ایک لمبے عرصہ تک اس قسم کی حیرت انگیز قربانی کی کوئی مثال نہیں ملتی.ا ورجب تک اس قسم کی مثال پیش نہیں کی جائے گی اس وقت تک دنیا کی الجھنوں کا حل بھی پیدا نہیں ہو گا.یہاں یہ سوال بھی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۂ ایلاف کیوں اتاری.قریش نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگیا.اس زمانہ میں قریش کی تعریف کرنے کے تو یہ معنے تھے کہ ان کو اور بھی مغرور کر دیا جائے.وہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھا ہمیں کافر کافر کہتے تھے مگر ہم نے کتنی قربانی کی.پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا.اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توجہ دلاتا ہے کہ تم بھی قربانی کا یہ نمونہ پیش کرو.پنجابی کی ایک مثال ہے.’’دِھیئے نی میں تینوں کَہْوَاں.نُہْویں نی تو کَن رَکھ.‘‘ یعنی ساس نے جب کوئی بات بہو سے کہنی ہو تو وہ بیٹی کو ڈانٹتی ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہو اس بات کو سن لے اور ہوشیار ہو جائے.اسی طرح قریش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو توجہ دلائے کہ کسی زمانہ میں ایک کافر اور مشرک قوم مکہ میں آکر بسی اور اس نے مکہ کو بسانے کے لئے ایسی حیرت انگیز قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی.بے شک ان میں یہ خوبی خدا تعالیٰ کے تصرّف سے پیدا ہوئی مگر تمہارے ساتھ بھی تو اس کا فضل ہے تمہیں بھی اس قربانی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اسلام کے لئے ایسی ہی قربانی پیش کرنی چاہیے اور ایسا ہی نمونہ دکھانا چاہیے جیسے ان لوگوں نے دکھایا.قادیان کو ہی لے لو.وہاں رہنے والے رہتے ہیں اور ہماری جماعت کے لوگ دوسروں کے سامنے تعریفیں بھی کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دیکھا ہم لوگوں نے کیا کیا.تم سب لوگ مشرقی پنجاب کو چھوڑ کر آگئے مگر ہم اب تک وہاں بیٹھے ہیں لیکن کہنے والے کو یہ خیال نہیں آتا کہ آیا یہ صرف دوسرے کا فرض ہے تیرا فرض نہیں.وہ دوسروں کے سامنے اس فعل کی تعریف کرتا ہے مگر جب اپنی باری آتی ہے تو کھسکنے لگتا ہے.صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ محض فخر لینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ورنہ کام کرنے کے لئے وہ تیار نہیں.وہ غیراز جماعت افراد میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے تم نے کبھی غور کیا کہ ہماری جماعت نے قادیان میں کیسا شاندار نمونہ دکھایا ہے.ہماری جماعت کتنی بڑی قربانی کر رہی ہے.وہ سنتا ہے اور تعریف کرتا ہے اس بیچارے کو کیا پتہ کہ ان لوگوں کی تنظیم کیسی ہے.اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ آگے سے جواب دیتا کہ وہ تو قربانی کر رہے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مگر اسے چونکہ علم نہیں ہوتا وہ محض ذکر سن کر متاثر ہو جاتا ہے.حالانکہ سوال یہ ہے کہ تم نے اس قربانی میں کیا حصہ لیا.اگر تم نے اس قربانی میں کوئی حصہ نہیں لیا تو
Page 449
وہ قربانی تمہارے لئے ملامت کا موجب تو ہو سکتی ہے فخر کا موجب نہیں بن سکتی.اگر وہ علی الاعلان کہہ دیتے کہ ہم قادیان نہیں جا سکتے ہم نے اینٹوں کو کیا کرنا ہے تو خواہ یہ جواب کتنا ہی غلط ہوتا وہ خدا تعالیٰ کے سامنے جا کر کہہ سکتے تھے کہ ہم نے جوکچھ کیا دیانتداری سے کیا.ہم یہی سمجھتے تھے کہ مومن کی جان زیادہ قیمتی ہوتی ہے اسے اینٹوں کی خاطر قربان نہیں کیا جا سکتا مگر جب وہ دوسروں کی قربانی کا ذکر سن کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگ جاتے ہیں تو اس کے معنے یہ ہیں کہ وہ بھی مانتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اچھا کیا.لیکن اس کے بعد جب اپنا سوال آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ یہ قربانی کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں.پس لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ والی آیات یہی سبق دینے کے لئے نازل ہوئی ہیں کہ خدا اب بھی اصحاب الفیل کا واقعہ دکھانے کے لئے تیار ہے مگر تم بھی تو قریش والا نمونہ دکھاؤ.میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں خدا ہمیں کب قادیان واپس دے گا اور کب اصحاب الفیل والا نشان ہمارے لئے ظاہر کرے گا.میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں اصحاب الفیل والا نشان کن لوگوں کے لئے ظاہر کیا گیا تھا ان لوگوں کے لئے جنہوں نے سوا دو سو سال تک وہ قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی انہوں نے اپنی جانیں دے دیں مگر مکہ نہ چھوڑا.وہ بھوک سے نڈھال ہو کر جب موت کے قریب پہنچ جاتے تو اپنا خیمہ اٹھاتے اور مکہ سے باہر چلے جاتے.ان کے سامنے ان کے بیوی بچے مر جاتے، ان کے سامنے ان کے بھائی مر جاتے، ان کے سامنے ان کی بہنیں مر جاتیں، ان کے سامنے ان کے دوست اور رشتہ دار مر جاتے مگر وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے.وہ اس تکلیف کی وجہ سے مکہ کو چھوڑتے بھی نہیں تھے.وہ ایک ایک کر کے مر گئے، مٹ گئے اور فنا ہو گئے مگر انہوں نے مکہ کو نہ چھوڑا.تم بھی یہ قربانی کرو تو خدا تمہارے لئے بھی اصحاب الفیل والا نشان دکھا دے گا بلکہ وہ تو غیر مومن تھے ان کے لئے دیر کے بعد نشان ظاہر ہوا تم مومن ہو تمہارے لئے یہ نشان جلد ظاہر ہو جائے گا.مگر پہلے قربانی کی مثال تو ہونی چاہیے پھر تمہارا بھی حق ہو گا کہ تم خدا سے کہو کہ ہم نے اپنی قربانی تو پیش کر دی ہے اب تو بھی ہماری تائید میں اپنا نشان دکھا.لیکن اپنا فرض ادا نہ کرنا اور خدا تعالیٰ سے کہنا کہ وہ وعدہ پورا کرے یہ کوئی دیانتداری نہیں.خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے اور یقیناً وہ سب سے زیادہ سچا ہے مگر وہ تبھی نشان دکھاتا ہے جب اس کے مقابلہ میں بندہ بھی قربانی پیش کرتا ہے مگر یہ روح ابھی جماعت میں کہاں ہے؟ جب تک یہ احساس قائم نہ ہو جائے اور پھر اس احساس کو دوسروں کے اندر قائم نہ کیا جائے اس وقت تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی.خلیفہ آخر کیا کر سکتا ہے.دو یا چار یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ آدمیوں کو سمجھانے کے لئے ایک ایک کے گھر پر تو نہیں جا سکتا.اس کا طریق تو
Page 450
یہی ہے کہ لوگ سنیں اور آگے پہنچائیں، وہ سنیں اور آگے پہنچائیں.جب تک وہی آگ ان کے دلوں میں بھی نہ لگ جائے، وہی تڑپ ان کے دلوں میں بھی پیدا نہ ہو جائے جو خلیفۂ وقت کے دل میں لگی ہوئی ہو اور جب تک ایک ایک احمدی دوسرے کو پکڑ کر یہ نہ کہے کہ تم میں فلاں غلطی ہے اس کی اصلاح کرو اس وقت تک یہ کام ہو ہی کس طرح سکتا ہے.دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی وفات کے قریب جب حجۃ الوداع میں لوگوں کو جمع کرکے ایک تقریر کی تو اس آخری وصیت میں آپ نے یہی کہا کہ فَلْیُبَلِّغُ الشَّاہِدُ الْغَائِبَ(بخاری کتاب الحج باب الخطبۃ ایام منٰی).میں نے بات کہہ دی ہے مگر میری بات سب لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی.میری بات اسی طرح دوسرے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی بات سنے وہ آگے پہنچائے وہ اگلا شخص پھر آگے پہنچائے.اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے.یہی قومی ترقی کا گُر ہے اسی سے قومیں زندہ ہوتی ہیں اِسی سے وہ دنیا میں فتح یاب ہوتی ہیں.ورنہ خلیفہ خلیفہ ہی ہے خدا نہیں.اب اس وقت میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کراچی والے اسے نہیں سن رہے.سندھ میں ہماری درجنوں جماعتیں ہیں وہ میری ان باتوں کو نہیں سن رہیں.پنجاب میں سینکڑوں جگہ پر جماعتیں ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سن رہیں.صوبۂ سرحد میں درجنوں مقامات پر احمدیہ جماعتیں ہیں وہ میری ان باتوں کو نہیں سن رہیں.ہندوستان اور مشرقی پاکستان میں سینکڑوں جگہ جماعتیں ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی میری یہ باتیں نہیں سن رہی.اس کے علاوہ ہندوستان سے باہر سینکڑوں جگہ جماعتیں ہیں مگر ان سب تک میری یہ آواز نہیں پہنچ رہی.بے شک تقریریں چھپ بھی جاتی ہیں مگر زبانی بات کا جو اثر ہو سکتا ہے وہ پڑھنے سے کہاں ہو سکتا ہے.پس جب ایک شخص سب دنیا تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتا تو پھر کون سا طریق ہے جس سے لوگوں کی اصلاح ہو.وہ طریق یہی ہے کہ ہر احمدی اپنے آپ کو دوسروں کی اصلاح کا ذمہ دار سمجھے.وہ رات اور دن اس کام میں لگا رہے اور اس غرض کے لئے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لئے تیار رہے.جب تم ایسا کر لو گے تو آسمان سے خدا تعالیٰ کا فضل نازل ہونا شروع ہو جائے گا اور تمہاری کامیابی تمہارے سامنے آجائے گی.اس وقت بھی ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ہم ساری دنیا میں تبلیغ کر سکتے ہیں.بلکہ اگر ہم اپنے اندر جانی قربانی کا صحیح جذبہ پیدا کر لیں، مالی قربانی کا صحیح جذبہ پیدا کر لیں تو ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ سکتے ہیں.تیسرے معنے اس آیت کے یہ ہوں گے کہ قریش کے دل میں جو سردی گرمی کے سفروں کی محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان کو بافراغت رزق ملتا ہے اور متمدّن اقوام سے ان کو تعلق پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے اس نعمت کو یاد کر کے انہیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خانۂ کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے.
Page 451
ان معنوں کے رو سے اس مضمون کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا کہ تمہارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ خانۂ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے ہو رہا ہے.کیونکہ جب کسی کام کا ایک نتیجہ بیان کر دیا جائے تو درحقیقت وہی نتیجہ اس کام کا اصل باعث ہوتا ہے.مثلاً ایک آقا اپنے نوکر کو تنخواہ دیتا ہے اگر کسی وقت وہ نوکر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو آقا اس سے کہتا ہے ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں تم کو چاہیے کہ تم ہماری فرمانبرداری کرو.اس کے دوسرے لفظوں میں یہ معنے ہوتےہیں کہ ہم تمہیں اس لئے تنخواہ دیتے ہیں کہ تم ہماری فرمانبرداری کرو.اسی طرح لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ کا نتیجہ یہاں فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ نکالا گیا ہے یعنی ہم نے ایلاف کیا اور اس کے اچھے سے اچھے نتائج پیدا کئے پس چاہیے کہ وہ رب البیت کی عبادت کریں.یہاں ’’پس‘‘ کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلا انعام پہلا اکرام اور پہلا احترام اسی غرض سے تھا کہ وہ رب البیت کے ساتھ تعلق رکھیں.پس اگر فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ کو لِاِيْلٰفِ کے ساتھ لگایا جائے جیسا کہ بہت سے نحوی یہی سمجھتے ہیں.تو اس صورت میں اس کے معنے یہ ہوں گے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک اس لئے کیا جاتا ہے کہ تم خدا کے گھر کو آباد رکھو اور اس کا ذکر کیا کرو.اس طرح ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تم اپنے متعلق یہ خیال نہ کر لینا کہ سلوک تمہاری کسی نیکی یا تمہاری کسی خوبی کی وجہ سے ہے.جیسے یہود میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ وہ خدا کے محبوب اور پیارے ہیں اس لئے ان سے نیک سلوک کیا جاتا ہے.قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں صرف چند دن سزا ملے گی.بعض کا یہ خیال تھا کہ ابراہیمی نسل میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا بعض کا یہ خیال تھا کہ انہیں صرف گیارہ مہینے سزا ملے گی بارہویں مہینے ہر ایک کو آزاد کر دیا جائے گا بعض کا یہ خیال تھا کہ ان کو صرف چالیس دن تک سزا ملے گی اور بعض کا یہ خیال تھا کہ انہیں بارہ دن سزا ملے گی.پھر بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ انہیں صرف سات دن سزا ملے گی (بحر محیط زیر آیت قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ....) اور بعض خیال کرتے تھے کہ یہودی جب دوزخ کے پاس لے جائے جائیں گے تو وہ خدا سے کہیں گے کہ اس تعلق کو یاد کر جو تجھے ہمارے باپ ابراہیمؑ سے تھا.اس پر خدا انہیں فوراً واپس لوٹا دے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا.اسی قسم کا خیال عربوں میں بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ چونکہ ہم ابراہیمؑ کی نسل میں سے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے.پس اس آیت میں اس کا ازالہ کیا گیا ہے.درحقیقت ہر قوم جب بداعمالی کی طرف راغب ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ کسی ٹوٹکہ کے ذریعہ سے ہی نجات حاصل کر لے.پس اللہ تعالیٰ فرتا ہے.لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ
Page 452
وَالصَّيْفِ.فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ (قريش:۲تا۴) ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے ان پر جو احسان کیا ہے یہ خانۂ کعبہ کی وجہ سے کیا ہے ان کی ذات کی وجہ سے نہیں کیا.ابراہیمؑ کی نسل ہونے کی وجہ سے ہم ان پر یہ فضل نہیں کر رہے تھے بلکہ اس لئے کر رہے تھے کہ اگر انہیں کھانے پینے کو بافراغت مل جائے گا توہ خدا کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے اوقات بسر کریں گے تاکہ آنے والے موعود پر ایمان لانے کے لئے تیار ہوتے رہیں.پس لِاِيْلٰفِ کا تعلق اگر فَلْيَعْبُدُوْا سے سمجھا جائے تو اس امر پر زور ثابت ہو گا کہ قومی برتری کوئی چیز نہیں.ان کا یہ خیال کہ یہ سب کچھ ہماری خاطر ہو رہا ہے بالکل غلط ہے.یہ خانۂ کعبہ کی خاطر، خانۂ کعبہ کے نبی کی خاطر اور ذکر ِ الٰہی کو قائم رکھنے کی خاطر ہو رہا ہے.ہم دیکھتے ہیں کہ اور قومیں تو الگ رہیں آج مسلمان بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں.جب اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی پر اپنا فضل نازل کرتا ہے تو اس کی سنت ہے کہ وہ اس فضل کا سلسلہ اس کی اولاد کے لئے بھی جاری کرتا ہے مگر آہستہ آہستہ وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم خدا کے خاص محبوب ہیں اور خدا کے محبوب کے وہ یہ معنے لیتے ہیں کہ جیسے عاشق کہتے ہیں ہمیں مار لو، پیٹ لو، دکھ دے لو ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے.اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ ہم خدا کو گالیاں دے لیں، خواہ ہم بے دینی کریں، خواہ ہم اس پر سَو سَو اعتراض کریں، خواہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، خواہ ہم اس کے کسی حکم کو نہ مانیں.اللہ تعالیٰ ہمارا عاشق ہے وہ ہمیں چھوڑ نہیں سکتا.چنانچہ مختلف شکلوں اور صورتوں میں لوگوں نے یہ عقیدہ قائم کیا ہوا ہے.حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ کی ایک بہن تھیں جو کسی پیر کی مرید تھیں.وہ ایک دفعہ آپ سے ملنے کے لئے آئی تو آپ نے اس سے کہا بہن تمہیں نماز کی طرف توجہ نہیں تم آخر خدا کو کیا جواب دو گی.اس نے کہا میں نے جس پیر کی بیعت کی ہوئی ہے اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ چونکہ تم نے میری بیعت کر لی ہے اس لئے اب تمہیں سب کچھ معاف ہے.آپ نے اپنی بہن سے کہا.بہن اپنے پیر صاحب سے پوچھنا کہ خدا کا حکم کس طرح معاف ہو گیا.نماز کا حکم تو خدا نے دیا ہےا ور وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا.آپ کی بیعت کرنے سے یہ حکم کس طرح معاف ہو گیا؟ اس نے کہا بہت اچھا جب میں جاؤں گی تو یہ بات ان سے ضرور دریافت کروں گی.کچھ مدّت کے بعد وہ پھر آپ سے ملنے کے لئے آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم نے اپنے پیر صاحب سے وہ بات دریافت کی تھی؟ اس نے کہا ہاں میں اپنے پیر صاحب کے پاس گئی تھی اور ان سے میں نے یہ بات دریافت کی تو وہ کہنے لگے تو نور دین سے ملنے گئی تھی.معلوم ہوتا ہے یہ شرارت تجھے نور دین نے ہی سکھائی ہے.میں نے کہا کسی نے سکھائی ہو آپ یہ بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن جس وقت خدا تم سے
Page 454
خدا اور اس کے رسول کا بس یہی کام ہے کہ وہ ڈاکوؤں کی طرح دوسروں کا مال لوٹ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں اور ان کی بہو بیٹیاں اغوا کر کے مسلمان نوجوانوں کو دیتے چلے جائیں تاکہ وہ عیاشیاں کریں.یہ کتنی بڑی بد عملی ہے جو غلط اعتقادات کی وجہ سے بعض مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اور کیا ایسی قوم دنیا میں کوئی بھی ترقی کر سکتی ہے.حالانکہ جہاں حقیقی محبت ہو وہاں کام زیادہ کیا جاتا ہے اور عام حالات سے زیادہ قربانی پیش کی جاتی ہے.مشرک لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کے لئے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اور طرح طرح کی تکالیف اٹھا کر انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.تو جہاں حقیقی محبت ہوتی ہے وہاں انسان کا م زیادہ کرتا ہے کام کو چھوڑ نہیں دیا کرتا.یہی بات اللہ تعالیٰ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ.فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ.الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ١ۙ۬ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (قريش:۲تا۵) کی آیت میں بیان فرماتا ہے.یعنی مکہ کے قریش اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان پر مہربانی کی، ان کے لئے امن قائم کیا، ان کی بھوک کو دور کیا اور ان کے لئے ہر قسم کے خطرات کو دنیا سے ہٹا دیا تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ رب البیت کی عبادت بھی کرتے.مگر ایک طرف تو یہ مانتے ہیں کہ خدا نے ان کے خوف کو دور کیا، خدا نے ان کی بھوک کو دور کرنے کے سامان مہیا کئے مگر دوسری طرف یہ اتنے نکمے ہو گئے ہیں کہ ہماری عبادت تک نہیں کرتے.ہم نے ان کے دلوں میں جو ایلاف کیا اور اس کے نتیجہ میں رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ کو قیام کیا.ان کے سفر نفع مند ہو گئے اور ان کی بھوکیں دور ہو گئیں انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں کیا گیا.آخر ہماری کوئی غرض تھی، کوئی مقصد تھا، کوئی وجہ تھی جس کی بناء پر ان سے یہ سلوک کیا گیا تھا.اور وہ وجہ یہی تھی کہ وہ اس گھر کو آباد رکھیں.پس چاہیے کہ جبکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تو یہ بھی اپنا حق ادا کریں اور عبادتِ الٰہی میں اپنا وقت گذاریں.حقیقت یہ ہے کہ یہ سفر بھی لوگوں کے دلوں میں حج کا شوق پیدا کرنے اور انہیں خانۂ کعبہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ تھے.جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں اہلِ عرب کو شروع میں حج کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں تھی.پس اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کو انہیں حج کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا.جب یہ لوگ ان کے گھروں میں جاتے اور ذکر کرتے کہ ہم مکہ سے آئے ہیں جہاں خانۂ کعبہ ہے اور جس کا اس اس طرح حج کیا جاتاہے اور جس سے بڑی بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو تمام عرب میں پراپیگنڈہ ہو جاتا اور وہ لوگ جو حج سے غافل تھے ان کے دلوں میں بھی حج کرنے کی تحریک پیدا ہو جاتی.اس طرح ان کو روزی بھی مل جاتی اور حج بھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ مقبول ہوتا چلا جاتا.
Page 455
چوتھے معنے اس کے یہ ہیں کہ تعجب ہے مکہ والوں نے اپنے نفسوں پر سردی اور گرمی کے سفر واجب کر چھوڑے ہیں اور بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے.یہ معنے بھی بعض مفسرین نے کئے ہیں یعنی تعجب ہے کہ یہ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ تو کرتے ہیں مگر عبادت نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ یہ ان سفروں کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گذاریں.مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ معنے درست معلوم نہیں ہوتے.اس لئے کہ ساری تاریخ اور خود عبارت کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہاں ان کے اس فعل کو برا نہیں کہا گیا بلکہ اسے اچھا قرار دیا گیا ہے اور جب ان کے اس فعل کو اچھا قرار دیا گیا ہے تو اس آیت کے یہ معنے نہیں ہو سکتے کہ وہ سفر کیوں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سفر چھوڑ دیں اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں پس یہ معنے لفظاً اور نحواً تو درست ہیں مگر یہاں چسپاں نہیں ہوتے.دوسرے وہ یہ سفر اس لئے کرتے تھے کہ روٹی کما کر لائیں اورپھر مکہ والوں میں بانٹیں تاکہ وہ مکہ میں ہی رہیں، تلاشِ معاش میں مکہ چھوڑ کر ادھر ادھر نہ چلے جائیں.اب ان معنوں کو درست تسلیم کرنے کا تو یہ مطلب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تم باہر جاؤ اور مکہ والوں کو کھلاؤ.مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ معنے عقل کے خلاف ہیں.اس لئے اس آیت کا ہرگز یہ مفہوم نہیں.ان سفروں کی ضرورت تو انہیں موت اور ہلاکت کی وجہ سے پیش آئی تھی.اگر بلاضرورت مکہ والے سفر کرتے تو اعتراض کی بات تھی مگر جبکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لئے انہوں نے یہ سفر اختیار کئے تھے تو اس آیت کے یہ معنے کرنا کہ وہ سفر کیوں کر رہے ہیں ان سفروں کو چھوڑیں اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کسی طرح بھی درست معلوم نہیں ہوتا.ہاں یوں یہ معنے درست ہو سکتے ہیں کہ ان معنوں کو زمانۂ نبوی سے مخصوص قرار دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ پہلے تو یہ سفر جائز تھے مگر اب تو مکہ والوں کو یہ سب کام چھوڑ کر صداقتِ محمدیت پر غو رکرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت میں لگ جانا چاہیے.اگر یہ معنے کئے جائیں تو یقیناً درست ہیں چنانچہ دیکھ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سفر خودبخود بند ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کو اتنا مقبول کر دیا کہ مکہ والوں کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہ رہی.وہیں بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ تجلّی کامل نہیں ہوئی تھی اس لئے مکہ والوں کو ان سفروں کی ضرورت پیش آتی رہتی تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تجلّی الٰہی کامل طور پر ظاہر ہو گئی اس لئے اب یہ ضرورت نہیں تھی کہ مکہ والے سفر کریں.اگر ہم اس آیت کے یہ محدود معنے کر لیں تو پھر کوئی اعتراض نہیں پڑتا.ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سفروں کو کلیۃً برا نہیں کہا بلکہ مکہ والوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہو رکے بعد اب ان سفروں کی کوئی ضرورت نہیں.تمہیں چاہیے کہ ان سفروں کو
Page 456
چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گذارو.ان معنوں کے رو سے یہ کفار پر ایک ضرب کاری اور مسلمانوں کی عظیم الشان تعریف ہے.آخر مومن بھی تو مکہ کے ہی رہنے والے تھے اور ان کی ضروریات بھی ویسی ہی تھیں لیکن وہ تو ایمان لاتے ہی سب کچھ چھوڑ کرتبلیغ حق اور خدمت دین میں لگ گئے اور جب وہ ایسا کر سکتے تھے تو مکہ کے اور لوگ ایسا کیوں نہیں کر سکتے تھے.ان معنوں سے پھر احمدیوں کے لئے ایک سبق نکلتا ہے.انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا مکہ والوں پر خدا تعالیٰ کا کوئی زیادہ احسان تھا جس طرح ان کو خدا تعالیٰ نے ناک، کان اور منہ دیئے تھے اسی طرح ہم کو اس نے ناک، کان اور منہ بخشے ہیں.جس طرح ان کو قویٰ عطا کئے گئے تھے اسی طرح ہم کو قویٰ دیئے گئے ہیں.جو علوم ان کو دیئے گئے تھے وہی علوم ہم کو دیئے گئے ہیں.جو قرآن ان کو دیا گیا تھا وہی قرآن ہم کو دیا گیا ہے.اس میں سے کوئی حصہ کم تو نہیں کردیا گیا.اگر مکہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے سارے کام کاج چھوڑکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو اور اپنے تمام اوقات خدمتِ دین میں صرف کرو تو یہ حکم مکہ والوں کےساتھ کوئی مخصوص تو نہیں تھا.جو حالت ان کی تھی وہی حالت ہماری ہے اور جو صداقت ان کے پاس تھی وہی صداقت ہمارے پاس ہے.جب ہماری جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام صداقتوں کا احیاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ فرمایا ہے تو سورۂ ایلاف میں جس صداقت کو پیش کیا گیا ہے لازماً ہمیں اس صداقت کا بھی از سرِ نو احیاء کرنا پڑے گا.ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سورۃ میں تو قریش مخاطب کئے گئے ہیں ہم ایسا کیوں کریں.اس لئے کہ ہماری جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ظلّی رنگ میں مبعوث فرمایا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت درحقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثت ثانیہ ہے.جب ہماری جماعت یہ تسلیم کرتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظِلِّ کامل ہیں تو ہماری جماعت کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ بیت اللہ کا.ظِلّ وہ مقام ہے جہاں خدا تعالیٰ کا نام روشن ہوتا ہے اور صحابہ کا.ظِل وہ جماعت ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے.اس صورت میں جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیت اللہ میں رہنےو الوں پر عائد ہو چکے ہیں یقیناً وہی فرائض ہماری جماعت پر بھی عائد ہوتے ہیں.دنیا میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو تمام بھائیوں میں سے بڑا بھائی اس کا قائم مقام بن جاتا ہے.اس وقت کوئی نہیں پوچھتا کہ ہمارا یہ بڑا بھائی باپ کا قائم مقام کس طرح بن گیا.کیونکہ عقل کہتی ہے کہ جب اصل سامنے نہ ہو تو بہرحال اس کا کوئی ظِلّ ہونا چاہیے اور پھر عقل یہ بھی کہتی ہے کہ
Page 457
جو ذمہ واریاں اصل پر عائد ہوتی ہیں وہی ذمہ واریاں ظِلّ پر بھی عائد ہوں گی.پس ہماری جماعت جب ظلّی رنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جماعت ہے اور ظِلِّ محمد پر ایمان لا کر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں تو ہمیں بھی ان آیات کا اپنے آپ کو ویسا ہی مخاطب سمجھنا پڑے گا جیسے صحابہؓ مخاطب تھے.اور ہمیں بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا جو صحابہؓ نے کیا.اللہ تعالیٰ ان آیات میں زمانۂ محمدی کے لوگوں سے کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ.تم کو چاہیے کہ تم عبادتوں میں اپنا وقت لگاؤ اور ذکر الٰہی کی عادت ڈالو.یہی کام احمدیوں کا ہے مگر افسوس ہے کہ احمدیوں نے اب تک اس مقام کو نہیں پایا کتنے احمدی ہیں جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں بے شک دوسروں سے زیادہ چندہ دینے والے احمدی موجود ہیں مگر چندہ سے تو دین نہیں پھیلتا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ دین کی ترقی تو نفس کی صفائی اور عبادت کی کثرت سے ہوتی ہے.مگر میں دیکھتا ہوں کہ ذکر الٰہی اور عبادت کی طرف بہت ہی کم توجہ ہے.فرض نمازیں بےشک وہ دوسروں سے زیادہ ادا کرتے ہیں مگر ذکر ِ الٰہی کرنا، مساجد میں بیٹھنا، راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرنا، اعتکاف کرنا.یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے اور جو نفس کی اصلاح کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتی ہیں.مگرہماری جماعت کی توجہ ان کی طرف بہت کم ہے.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کیں ان میں بھی آتا ہے کہ الٰہی تیرے لئے اعتکاف کرنے والے لوگ اور تیری عبادت میں اپنا وقت گذارنے والے لوگ میری اولاد میں ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں.مگر میں دیکھتا ہوں کہ احمدیوں کو اس طرف بہت کم توجہ ہے حالانکہ جب تک ان باتوں کی طرف توجہ نہ ہو انسان کا نفس کبھی جلا نہیں پاتا.جلاءِ نفس ہمیشہ ذکرِ الٰہی سے ہوتا ہے.نمازوں کے متعلق بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس امر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی کہ نمازیں آہستگی کے ساتھ پڑھیں.لوگ سنتیں جلدی جلدی ختم کر کے مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں.لاہور میں جن دنوں اُمِّ طاہر بیمار تھیں میں متواتر جماعت کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا رہا اور میں نےد یکھا کہ آخر پندرہ بیس دن کے بعد جماعت کو یہ عادت ہوئی کہ وہ آہستہ آہستہ نماز پڑھے امام کے ساتھ تو آہستہ نماز پڑھنے پر لوگ مجبور ہوتے ہیں ورنہ اگر ان کا بس چلے تو امام رکوع میں ہی ہو اور وہ سلام پھیر کر چلے جائیں.لیکن جب فرض نماز ختم ہوتی ہے اور سنتیں پڑھنے کا وقت آتا ہے تو جھٹاپٹ ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے جو نہایت نامناسب اور اسلامی تعلیم کے خلاف حرکت ہے ہماری جماعت کے دوستوں کا فرض ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر نمازیں پڑھا کریں اور اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ ذکر الٰہی اور دعاؤں میں صرف کیا کریں اور دوسرے مسلمانوں سے بھی انہیں یہی کہنا چاہیے کہ وہ عبادت اور ذکر الٰہی پر زور دیں.کیونکہ اسلام کی اصل ترقی ذکر الٰہی اور عبادت پر زور دینے سے ہی ہو گی.
Page 458
تاریخوں سے ثابت ہے کہ جب رومی سفیر مسلمانوں کی حالت دیکھ کر واپس گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے مقابلہ میں جیت نہیں سکتے.اس نے پوچھا کیوں؟ رومی سفیر نے جواب دیا کہ وہ تو سارا دن لڑتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتے ہیں.وہ آدمی نہیں بلکہ جِنّ معلوم ہوتے ہیں.حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر زور دینا ایسا نور پیدا کر دیتا ہے جس سے پہلے انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے اور پھر وہ دنیا کی اور طاقتوں کو مغلوب کر لیتا ہے.آج کل کے لوگ مغربی تہذیب کے ماتحت یہ سمجھتے ہیں کہ ذکرِ الٰہی وغیرہ کرنا اور مصلّٰے پر بیٹھے رہنا وقت کو ضائع کرنا ہے.حالانکہ یہ مصلّٰے پر بیٹھ کر ذکر الٰہی کرنے والے ہی تھے جنہوں نے بارہ سال کے اندر اندر آدھی دنیا تہ و بالا کر دی.اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ مصلّٰے پر بیٹھنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا بلکہ انسان کو ایسی برکت ملتی ہےکہ وہ بڑے بڑے کام تھوڑے سے وقت میں کر لیتا ہے.پس مصلّٰے پر بیٹھنے کے معنے نکما پن کے نہیں بلکہ درحقیقت اس سے ایسی مہارت پیدا ہو جاتی ہے اور دل میں اس قسم کا نور پیدا ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں انسان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے.اگر تین گھنٹے وہ ذکر الٰہی میں مصروف رہتا ہے تو بےشک بظاہر اس کے تین گھنٹے وقت میں سے کم ہو جائیں گے مگر انہی تین گھنٹوں کی بدولت وہ آٹھ گھنٹوں میں وہ کچھ کام کر لے گا جو باقی ۲۴ گھنٹوں میں بھی نہیں کر سکیں گے.پس عبادت کی کثرت تہجد اور ذکرِ الٰہی کی طرف توجہ کرو اور اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لئے وقف کرو.میں بتا چکا ہوں کہ ابھی ہماری جماعت میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہوںنے خدمت دین کے لئے اپنی زندگیاں وقف کی ہوں اور پھر جو اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں ان میں سے بھی ایک حصہ ایسا ہے جو اپنے فرائض کو نہیں سمجھتا.مثلاً کوئٹہ کی جماعت کو ہی لے لو.یہ جماعت بہت سی جماعتوں سے اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض کاموں میں اس نے نہایت شاندار نمونہ دکھایا ہے مگر جہاں تک زندگی وقف کرنے کا سوال ہے ابھی وہ بھی اس میں بہت پیچھے ہے.اس معاملہ میں سب بڑی ذمہ واری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندان پر ہے.میں صرف دوسروں پر اعتراض نہیں کرتا.میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندان کے افراد کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں.میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے بھی ایک حصہ اس فرض کو بھول کر دنیوی کاموں اور تجارتوں میں مشغول ہو گیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں.لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو بگاڑنے والی زیادہ تر جماعت ہے جو ان کو صاحبزادے صاحبزادے کہہ کر خراب کر دیتی ہے.حالانکہ جو صاحب کو بھول گیا وہ
Page 459
زادہ کہاں سے آگیا.وہ دوکانیں کر رہے ہیں، وہ تجارتیں کر رہے ہیں، روپیہ کمانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور جب انہیں کہا جائے کہ تم دین کے لئے اپنی زندگی کیوں وقف نہیں کرتے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم زندگیاں وقف کریں توگذارہ کس طرح کریں گویا دوسرا شخص اگر تیس روپیہ لے کر گذارہ کر سکتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے تھوڑے روپوں میں گذارہ نہیں کر سکتے.حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ بھی رکھا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا یہی منشا ہے کہ آپ کی اولاد اسماعیلی نمونہ کو اختیار کرے اور دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دے.اس کے بعد خدا انہیں زیادہ دے تو وہ زیادہ قبول کر لیں اور اگر کم دے تو کم پر راضی رہیں یہ خدا تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے.حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے بعض فاقہ زدہ نبی بھی ہوئے ہیں اور حضرت سلیمانؑ جیسے بادشاہ بھی گذرے ہیں جن کے لشکروں اور نوکروں کی تعداد ہی ہزاروں تک پہنچتی تھی.میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جماعت کے سفلی طبع لوگ یا منافق طبقہ ان کو تو ادنیٰ نگاہ سے دیکھتا ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں اوران کی تعریف کرتا ہے جو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں.میں خوب سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایک حصہ جاہل ہے اور دوسرا منافق.جو اس طرح جماعت کو تباہ کرنا چاہتا ہے.مگر میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا فعل ایک دن ایسے سب لوگوں کو خس کم جہاں پاک کر دے گا.کیونکہ مومنوں کا دور ابھی آنا ہے.بہرحال میں جماعت کو یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارہ میں ہماری جماعت خطرناک کوتاہی کا ارتکاب کر رہی ہے.دین کی خدمت کے لئے جتنے لوگوں کو اپنی زندگی وقف کرنی چاہیے اتنے لوگ اپنی زندگی وقف نہیں کر رہے اور پھر جو زندگی وقف کرتے ہیں وہ بھی اپنے فرائض کو پورے طور پر ادا نہیں کر رہے.حالانکہ جب تک اس امر کی طرف توجہ نہیں ہو گی ہمارا کبھی بھی وہ پیمان پورا نہیں ہو گا جو ہم خدا کے ساتھ بیعت کے وقت کرتے ہیں.اور جب تک ہم اپنے پیمان کو پورانہیں کرتے اس وقت تک خدا تعالیٰ کا ہمارے متعلق جو عہد ہے اس کے بھی ہم کبھی حقدار نہیں ہو سکتے.اب میں پھر نفسِ مضمون کی طرف آتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ نتیجہ ہے لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ کا.یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اہل مکہ سے احسان اور سلوک اسی لئے کیا تھا کہ وہ ہماری عبادت کرتے.آخر کیا حق تھا ان کا ہم پر کہ ہم دوسروں کے مقابلہ میں ان سے نمایاں سلوک کرتے.کیا یورپ والے ہمارے دشمن تھے.کیا ہندوستان والے ہمارے دشمن تھے.کیا حبشی ہماری مخلوق نہیں تھے؟ پھر کیوں ہم نے ان کی ترقی کا خاص سامان کیا؟ اسی لئے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس رہتے ہیں.تا ایسا نہ ہو کہ انہیں روٹی کی تکلیف ہو اور وہ اس مقام کو چھوڑ کر بھاگ جائیں.مگر دیکھو ہم تو انہیں روٹی دیتے رہے مگر انہوں نے ہمارا خیال نہ
Page 460
رکھا حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اس احسان کے بدلے میں وہ رب البیت کی عبادت کرتے اور ہمارے احسانات کی قدر کرتے.یہاں رب البیت کیوں کہا ہے؟ صرف بیت کیوں نہیں کہا.اس لئے کہ قرآن کریم اس بات کا قائل نہیں کہ کوئی بے جان چیز اپنے اندر طاقتیں رکھتی ہے.وہ طاقتوں کا مالک صرف خدا تعالیٰ کو سمجھتا ہے.پس توحید کامل کا سبق دینے کے لئے یہاں رب البیت کے الفاظ رکھے گئے ہیں.یعنی مکہ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیت کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز حاصل ہو اہے حالانکہ یہ اعزاز انہیں بیت کی وجہ سے نہیں بلکہ رب البیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے.گویا نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ خانۂ کعبہ نے کچھ کیا ہے خانۂ کعبہ کچھ نہیں کر سکتا وہ مٹی کا ایک مکان ہے اور اس میںیہ طاقت ہرگز نہیں کہ وہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے.اس گھر کا رب ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے.احادیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے کہ آپ حجرِ اسود کے پاس سے گذرے اور آپ نے اسے اپنی سوٹی ٹھکرا کر کہا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اور تجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں مگر میں خدا کے حکم کے ماتحت تجھے چومتا ہوں.یہی جذبۂ توحید تھا جس نے ان کو دنیا میں سربلند کیا.وہ خدائے واحد کی توحید کے کامل عاشق تھے.وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اس کی طاقتوں میں کسی اور کو شریک کیا جائے بے شک وہ حجرِ اسود کا ادب بھی کرتے تھے مگر اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے اس کا ادب کرو.نہ اس لئے کہ حجرِ اسود کے اندر کوئی خاص بات ہے.وہ سمجھتے تھے کہ اگر خدا تعالیٰ ہمیں کسی حقیر سے حقیر چیز کو چومنے کا حکم دے دے تو ہم اس کو چومنے کے لئے بھی تیار ہیں کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے ہیں کسی پتھر یا مکان کے بندے نہیں.پس وہ ادب بھی کرتے تھے اور توحید کو بھی نظرانداز نہیں ہونے دیتے تھے اور یہی ایک سچے مومن کا مقام ہے.ایک سچا مومن بیت اللہ کو ویسے ہی پتھروں کا ایک مکان سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور ہزاروں مکان پتھروں کے بنے ہوئے ہیں.ایک سچا مومن حجرِ اسود کو ویسا ہی پتھر سمجھتا ہے جیسے دنیا میں اور کروڑوں پتھر موجود ہیں مگر وہ بیت اللہ کا ادب بھی کرتا ہے، وہ حجرِ اسود کو چومتا بھی ہے.کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے ان چیزوں کے ادب کرنے کا مجھے حکم دیا ہے مگر باوجود اس کے کہ وہ اس مکان کا ادب کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ حجرِ اسود کو چومتا ہے پھر بھی وہ اس یقین پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ میں خدائے واحد کا بندہ ہوں کسی پتھر کا بندہ نہیں.یہی حقیقت تھی جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اظہار فرمایا.آپ نے حجرِ اسود کو سوٹی ماری اور کہا میں تیری کوئی حیثیت نہیں سمجھتا.تو ویسا ہی پتھر ہے جیسے اور کروڑوں پتھر دنیا میں نظر آتے ہیں.مگر میرے رب نے کہا ہے کہ تیرا ادب کیا جائے اس لئے میں ادب کرتا
Page 461
ہوں.یہ کہہ کر وہ آگے بڑھے اور اس پتھر کو بوسہ دیا اس کا مطلب یہی تھا کہ خدا نے تیرا ادب سکھایا ہے اس لئے میں ادب کرتا ہوں ورنہ تیرے اندر ذاتی طو رپر کوئی ایسی طاقت نہیں جس کی بناء پر تجھے چوما جا سکے جب اس احساس کے ساتھ ہم حجرِاسود کو چومتے ہیں کہ ہمارے خدا نے اس کو چومنے کا حکم دیا ہے ورنہ وہ ایک معمولی پتھر ہے تو ہم توحید پر قائم ہوتے ہیں.اور جب ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس پتھر کو کسی خاص خوبی کا مالک سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا یہی فعل مشرکانہ فعل بن جاتا ہے.حضرت عمرؓ نے حجرِ اسود کو چوما مگر وہ مشرک نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حجرِ اسود اپنی ذات میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا.میرے رب کا حکم مجھے لایا اور میں نے اسے چوما.لیکن اگر کوئی دوسرا شخص حجرِ اسود کو چومتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ حجرِ اسود میں کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اسے چوما جاتا ہے تو وہی شخص مشرک بن جائے گا.اگر ایک شخص خانہ کعبہ کا اس لئے طواف کرتا ہے کہ میرے خدا نے اس کے طواف کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ بڑا مؤحد ہے اور اگر کوئی شخص خانۂ کعبہ کا اس لئے طواف کرتا ہے کہ اس گھر میں کوئی خاص طاقت ہے تو وہ مشرک ہے یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے کہ تم سمجھتے ہو اس بیت کی وجہ سے تمہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے احمقو! یہ سب کچھ اس بیت نے نہیں کیا بلکہ رب البیت نے کیا ہے.اس گھر کو تو خدا نے محض ایک علامت کے طور پر مقرر کیا ہے.جیسے پرانے زمانہ میں دستور تھا کہ بادشاہ کسی بکرے یا اونٹ وغیرہ پر اپنا نشان لگا کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اس کو نقصان پہنچا سکے اور اگر کوئی اس کو نقصان پہنچاتا تو اس کے معنے یہ ہوتے تھے کہ بادشاہ کی ہتک کی گئی ہے.چنانچہ جب کوئی مخالف بادشاہ اس بکرے یا اونٹ کو مار ڈالتا تو اس سے لڑائی شروع ہو جاتی تھی.اس لئے نہیں کہ اس نے اونٹ کو مارا ہے اس لئے نہیں کہ اس نے گھوڑے کو مارا ہے، اس لئے نہیں کہ اس نے بکرے کو مار اہے، اس لئے نہیں کہ اس نے دنبہ کو مارا ہے بلکہ اس لئے کہ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ اس نے میری ہتک کی ہے.اسی طرح بیت اللہ کو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمّت کے لئے ایک مرکز اور اولادِ ابراہیم ؑ کو جمع رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے.پس وہ خدا کی ایک علامت ہے جو دنیا میں پائی جاتی ہے.اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس گھر میں کوئی خاص بڑائی پائی جاتی ہے تو وہ مشرک ہے اور اگر کوئی شخص اس کی یہ سمجھ کر ہتک کرتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ نشانی نہیں تو وہ خدا کا بھی دشمن ہے.ایک سے وہ معاملہ کیا جائے گا جو مشرکوں سے کیا گیا اور دوسرے سے وہ معاملہ کیا جائے گا جو اصحاب الفیل سے کیا گیا.صرف اسی شخص کا نقطۂ نگاہ صحیح سمجھا جائے گا جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ کیا رب البیت نے کیا ہے بیت نے نہیں کیا.اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ.جو کچھ مکہ والوں سے سلوک ہو رہا ہے اس کی وجہ رب البیت کے سوا کوئی نہیں.اگر
Page 462
اس گھر کا کوئی رب نہ تھا تو اصحاب الفیل کو کس نے تباہ کیا، اگر رب البیت نہ تھا تو مکہ کی حفاظت اس طرح صدیوں تک کس نے کی، اگر رب البیت نہ تھا تو مکہ والوں کو رزق کس نے مہیا کیا، اگر رب البیت نہ تھا تو ان کے ان سفروں میں یہ برکات کس طرح رکھی گئیں، اگر رب البیت نہ تھا تو آنےو الے موعود کی یاد دلانے کے لئے جس کی خاطر یہ گھر بنایا گیا تھا مکہ والوں کو ان ملکوں سے کس نے روشناس کروایا.پس جب تمہارے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہا ہے خدا تعالیٰ کر رہا ہے تو یہ کیسی قابلِ شرم حرکت ہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر لات اور منات اور عزّیٰ کی پرستش کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ خانۂ کعبہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہم جو جی چاہے کر لیں ہمارے لئے جائز ہے.تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس خانۂ کعبہ کی عزت بھی رب البیت کی وجہ سے ہے اور جب اس کی عزت بھی رب البیت سے وابستہ ہے اور اسی نے تم کو ترقیات بخشی ہیں تو کیا تمہارا فرض نہیں کہ تم شرک چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو.گویا عبادت اور توحید دونوں پر اس آیت میں زور دیا گیا ہے.کہا جا سکتاہے کہ جھوٹے معبودوں اور مندروں اور پجاریوں کی بھی تو دنیا میں عزت کی جاتی ہے.پھر کیا وہ عزت بھی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ بتوں نے ان کو عزت دی ہے یعنی تم یہ کہتے ہو کہ وہ اس خانہ کعبہ کی عزت رب البیت کی وجہ سے ہے حالانکہ دنیا میں ایسے مندر بھی موجود ہیں جن کی بڑی عزت کی جاتی ہے پھر کیا ان کی عزت بھی ان کے بتوں کی طرف منسوب ہو سکتی ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان بتوں نے ان کو عزت دی ہے.اس کا جواب یہ ہے کہ جھوٹی اور سچی چیزیں ایک ہی وقت میں دنیا میں موجود رہتی ہیں.سونا بھی موجود ہوتا ہے اور ملمّع بھی موجود ہوتا ہے مگر کیا ملمّع کی وجہ سے لوگ سونے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں؟ اسی طرح دنیا میں سیپ کے بنے ہوئے موتی بھی موجود ہیں اور اصلی موتی بھی موجود ہیں نقلی ہیرا بھی موجود ہے اور اصلی ہیرا بھی موجود ہے.ایسی صورت میں ہم کیا کرتےہیں کیا ہم اصلی چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں یا ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی امتیازی علامات ہیں جن پر پرکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ جھوٹا کون سا ہے اور سچا کون سا ہے ہم جھوٹے موتیوں کی وجہ سے اصلی موتیوں کو چھوڑانہیں کرتے.ہم جھوٹے ہیروں کی وجہ سے اصلی ہیروں کو چھوڑا نہیں کرتے.ہم جھوٹے سونے کی وجہ سے اصلی سونے کو چھوڑا نہیں کرتے.بلکہ ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے امتیازی نشانات ہیں جن پر پرکھ کر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ نقلی چیز کون سی ہے اور اصلی چیز کون سی.اسی طرح اس معاملہ میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ عزت جو خانۂ کعبہ کو حاصل ہوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی یا نہیں اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی تو اس کا امتیازی نشان کیا تھا جو اسے دوسرے معبدوں اور مندروں سے ممتاز کر دے.
Page 463
اسی کو ایک اور مثال سے یوں سمجھ لو کہ ماں باپ بچے کو پالتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت بچہ سے طبعی محبت کا ثبوت ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ ٹھگ بچہ چرا کر لے جاتے ہیں اور بچہ کو آئندہ کی شرارت کی غرض سے پالتے ہیں.وہ اس کو بداخلاق، چور اور ڈاکو بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر بہرحال وہ پالتے محبت سے ہیں.اگر ماں باپ کی طرح محبت سے نہ پالیں تو وہ فوراً بھاگ جائے گویا وہ محبت تو کرتے ہیں مگر ان کی محبت جھوٹی ہوتی ہے.اب کیا ان کا پالنا اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کو بھی بچہ سے محبت نہیں ہوتی.حقیقت یہ ہے کہ جس طرح اصلی اور نقلی چیزوں میں بڑا بھاری فرق پایا جاتا ہے اسی طرح جھوٹے معبودوں اور مندروں اور پجاریوں کی عزت اور اس عزت میں بڑا بھاری فرق ہے جو خانۂ کعبہ کو حاصل ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ خانۂ کعبہ اتفاقی طور پر معزز نہیںہو ابلکہ خانۂ کعبہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے الہام سے رکھی گئی.چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ ( اٰلِ عـمران:۹۷)یہ سب سے پہلا گھر تھا جو سب دنیا کے فائدہ کے لئے بنایا گیا تھا.یہ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے کے قومی مذہب ایسا گھر نہیں بنا سکتے جو سب دنیا کے لئے ہو.ایسا گھر خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے اور اسی کے الہام سے مقرر کیا جا سکتا ہے.اس کے بعد زمانۂ ابراہیمی میں پھر خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق اس کی عمارت کی تجدید ہوئی چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں خداکے لئے اس گھر کو بناتا ہوں اور اس لئے بناتا ہوں کہ یہاں لوگ آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے گھر کا طواف کریں، عبادت اور ذکر الٰہی میں اپنا وقت بسر کریں اور آنے والوں کی خدمت کریں.پھر انہوں نے دعا کی کہ خدایا تو بھی اس گھر کو امن دیجئو اور اس کے رہنے والوں کو اپنے پاس سے رزق دیجئواور پھر ان میں سےایک نبی پیدا کیجئو جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے یہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت کی.اس وقت کی جب خانۂ کعبہ کی ترقی کے کوئی آثار نہ تھے، اس وقت کی جب اس کی آبادی کے کوئی آثار نہ تھے، اس وقت کی جب وہ محض ایک وادیٔ غیر ذی زرع تھی، اس وقت کی جب اس میں پانی کا ایک گھونٹ اور گندم کا ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا.پس اس کے بعد خانۂ کعبہ کی جو کچھ ترقی ہوئی اسے یقیناً ہم اس دعا اور پیشگوئی کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سلوک محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا.اس کے مقابلہ میں دنیا میں بے شک لاکھوں مندر موجود ہیں مگر کیا ان میں سے کوئی ایک مندر بھی ایسا ہے جس کی ترقی کسی پیشگوئی کے ماتحت ہوئی ہو.یا کیا ان مندروں میں سے کوئی ایک مندر بھی ایسا ہے جس کو ماننے والے آج ہی اس قسم کی پیشگوئی دنیا میں شائع کر سکیں.اگر ان میں ہمت اور طاقت ہے تو وہ ایسی پیشگوئی
Page 464
کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے.یوں کسی مندر کی عزت ہونا اور بات ہے اور پیشگوئی کے ماتحت عزت ہونا اور بات ہے.اگر ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے قبل از وقت کہہ دیتا ہے کہ ابھی زید آئے گا اور پھر واقعہ میں زید آجاتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میری بات پوری ہو گئی.لیکن ایک اور شخص جو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اگر وہ کہے کہ دیکھو میری بات پوری ہو گئی زید آگیا ہے تو ہر شخص اس پر ہنسے گا کہ تم نے یہ بات ہی کب کی تھی کہ زید کے آنے پر تم کہہ رہے ہو کہ میری بات پوری ہو گئی ہے اسی طرح خانۂ کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیشگوئی کی.اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ خانہ کعبہ ترقی کرے گا.یہ بھی ذکر تھا کہ لوگ یہاں حج اور طواف کے لئے آئیں گے.یہ بھی ذکر تھا کہ لوگ یہاں بسیں گے.یہ بھی ذکر تھا کہ اس گھر کو محفوظ رکھا جائے گا اور کوئی دشمن اسے تباہ نہیں کر سکے گا.یہ بھی ذکر تھا کہ اس مقام پر رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جائے گا جب ایک ایک کر کے تمام پیشگوئیاں پوری ہو گئیں اور پھر مخالف حالات میں پوری ہوئیں تو یقیناً ان پیشگوئیوں کا پورا ہونا اپنی ذات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ خانۂ کعبہ سے جو کچھ سلوک ہوا وہ اتفاقی نہیں تھا بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا.لیکن دوسرے مندروں میں سے اگر کسی کو کوئی عزت حاصل ہوئی ہے تو چونکہ اس کے ساتھ کوئی پیشگوئی نہیں تھی اس لئے اسے محض اتفاق پر محمول کیا جائے گا.پھر خانۂ کعبہ کا محل وقوع دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جس کے اردگرد بھی میلوں میل تک کوئی آبادی نہیں تھی.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں پانی موجود نہیں تھا.حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ یہ گھر بنایا جہاں کھیتی موجود نہیں تھی.گویا خدائی ہاتھ کا ثبوت دینے کے لئے جو جگہ ہر قسم کی ترقی کے سامانوں سے محروم تھی وہی جگہ اس گھر کے لئے تجویز کی گئی.پانی آبادی کے لئے ضروری ہوتا ہے مگر وہاں پانی نہیں تھا.کھیتی آبادی کے لئے ضروری ہوتی ہے مگروہاں کھیتی نہیں تھی.شہر اور اردگرد کی آبادی، آبادی کے لئے ضروری ہوتی ہے مگر وہاں نہ کوئی شہر تھا اور نہ اس کے اردگرد کوئی آبادی تھی.ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دنیا میں یہ اعلان کرنا کہ یہاں لوگ آئیں گے اور حج بیت اللہ کریں گے اور پھر لوگوں کا وہاں آنا اور حج بیت اللہ کرنا اور ایک غیرآباد مقام کا آباد ہو کر ایک بہت بڑا شہر بن جانا بتاتا ہے کہ جو کچھ ہوا رب البیت کی طرف سے ہوا.اس کے مقابلہ میں اتفاقی طور پر اگر کسی مندر کو شہرت حاصل ہو جاتی ہے تووہ ہرگز اس مندر کے کسی بت کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی.کیونکہ کب اس مندر کی عظمت کے متعلق پیشگوئی کی گئی تھی.کب یہ کہا گیا تھا کہ اس کی لوگوں میں شہرت ہو جائے گی اور کب کسی قوم اور مذہب نے اس دعویٰ کی سچائی پر اپنی عزت
Page 465
اور اپنی سچائی کی بازی لگائی تھی.پس اسے اگر شہرت حاصل ہوئی ہے تو محض اتفاقی طور پر.جیسے لنڈن ایک بہت بڑا شہر بن گیا.مگر اس کے لئے کوئی پیشگوئی نہیں تھی.نیویارک ایک بہت بڑا شہر بن گیا مگر اس کے لئے کوئی پیشگوئی نہیں تھی.بے شک وہ بہت بڑے شہر ہیں مگر ان کی ترقی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی.لیکن اگر لنڈن سے پچاسویں حصہ کے برابر بھی کوئی شہر اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی کے مطابق آباد ہوتا ہے تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کا نشان قرار دیں گے.پس کسی مندر کی مقبولیت اور خانہ کعبہ کی مقبولیت میں بڑا بھاری فرق ہے.خانہ کعبہ کی مقبولیت خدائی پیشگوئیوں کے مطابق ہوئی ہے لیکن مندروں کی مقبولیت محض ایک اتفاقی امر ہے جس طرح سونے کے مقابلہ میں ملمّع ہوتا ہے اسی طرح خانہ کعبہ کی عظمت کے مقابلہ میں کسی مندر کی عظمت یا اس کی ترقی بھی ایک ملمّع سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی.فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ۰۰۴ پس انہیں لازم ہے کہ وہ (یعنی قریش) اس گھر (یعنی کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں.الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ١ۙ۬ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍؒ۰۰۵ جس نے انہیں (ہر قسم کی) بھوک (کی حالت) میں کھانا کھلایا اور (ہر قسم کے ) خوف کی حالت میں امن بخشا.تفسیر.اس آیت نے اس مضمون کو بالکل واضح کر دیا ہے جس پر میں شروع سے زور دیتا چلا آرہا ہوں.میں نے بتایا تھا کہ یہاں اصل ذکر خدا کی خدائی اور اس کی طاقت و قوت اور اس کے فضل اورا حسان کا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ کی محبت پیدا کی اور وہ خدا ہی ہے جس نے انہیں سفر کی سہولتیں مہیا کر کے عزت اور شہرت دی.اب اس آیت میں اوپر کے اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب قریش پر ہم نے اس قدر احسانات کئے ہیں تو کیا ان کا فرض نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں.اس خدا کی عبادت الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ١ۙ۬ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ جس خدا نے انہیں بھوک پر کھانا کھلایا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیا.عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ کبھی اشارۂ قریب کا ذکر پہلے آجاتا ہے اور اشارۂ بعید کا ذکر بعد میںآتا ہے اور کبھی ترتیب کلام کو مدّ ِنظر رکھا جاتا اور اسی کے مطابق اشارہ لایا جاتا ہے.یہ دونوں طریق عربی زبان میں مروّج ہیں
Page 466
اور دونوں طرح ضمائر کا استعمال ہوتا ہے.اس جگہ اشارۂ قریب کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور اشارۂ بعید کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے.اشارۂ قریب لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ قریش بھوکے مرتے تھے ہم نے انہیں روٹی کھلائی.پس چونکہ روٹی کا قریب میں ذکر آتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے روٹی کا ہی ذکر کیا اور فرمایا الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ.اس کے بعد دوسرا اشارہ جو اشارۂ بعید ہے.سورۃ الفیل کی آخری آیت فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ کی طرف تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو بھوسہ کی طرح اڑا دیا.اگر ابرہہ کے لشکر کا کلّی استیصال نہ کیا جاتا تو یمن سے مکہ کو مستقل خطرہ رہتا اور یمن کا سفر مکہ والوں کے لئے بالکل ناممکن ہو جاتا.اسی طرح یمن سے لڑائی کی وجہ سے شام کا سفر بھی ناممکن ہو جاتا کیونکہ یمن بھی روم کا صوبہ تھا.پس چونکہ اس صورت میں مکہ والوں کے لئے یہ دونوں سفر ناممکن ہو جاتے.اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا پُر ہیبت نشان دکھایا کہ یمن کی مسیحی حکومت بالکل تباہ ہو گئی اور شام پر بھی رعب طاری ہو گیا اور مکہ والوں کے دونوں سفر قائم رہے پس چونکہ یہاں اشارۂ بعید فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ کی طرف تھا اور اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر کرنا چاہتا تھا جو اس نے اصحاب الفیل کو تباہ کر کے مکہ والوں پر کیا اس لئے اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ کا ذکر اس نے اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ کے بعد کیا.اس آیت نے سورۃ الفیل کی آخری آیت کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یہ بھی بتا دیاہے کہ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ.اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ کے جو مختلف معانی کئے گئے ہیں وہ سب کے سب درست ہیں.یعنی اس سورۃ میں ایک مستقل مضمون بھی بیان کیا گیا ہے اور اس میں پہلی سورۃ کے مضمون کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ نے سورۂ ایلاف کے مستقل مضمون کی طرف اشارہ کر دیا اور اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ نے سورۃ الفیل کی طرف اشارہ کر دیا.گویا یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کو ایلافِ قریش کی غرض سے تباہ کیا اور یہ بھی درست ہے کہ ان کے دلوں میں رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ کے متعلق رغبت پیدا کی تاکہ ان کو روٹی مل جائے اورمکہ میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں.بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے ان دونوں انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا.جو تمہارے قافلوں کو شام اور یمن کی طرف لے گیا اور اس طرح اس نے تمہارے لئے روٹی کا سامان کیا.اسی طرح تم اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہارے خوف کو امن سے بدل دیا یعنی اصحاب الفیل جب حملہ کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کیا اور تمہارے لئے اس نے امن کی صورت پیدا کی.
Page 467
مِنْ جُوْعٍ میں مِنْ کا لفظ کیوں رکھا گیا ہے اور جُوْعٍ پر تنوین کیوں آئی ہے؟ اس کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں اور دونوں ہی اس جگہ چسپاں ہوتی ہیں.پہلی یہ کہ تنوین تعظیم کے لئے آتی ہے.اگر اس امر کو مدّ ِنظر رکھا جائے تو الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ کے یہ معنی ہوں گے کہ اے اہل مکہ ہم نے تم کو ایک ایسی خطرناک بھوک سے بچایا ہے جس سے تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی.واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایک وادیٔ غیر ذی زرع میں پڑے ہوئے تھے.ایسے غیرآباد خطہ میں رہتے ہوئے وہ بھوک کی موت سے کہاں بچ سکتے تھے.طائف میں بے شک باغات وغیرہ تھے اور وہاں کسی قدر زراعت بھی ہوتی تھی مگر یہ زراعت بہت ناکافی تھی.مکہ کے صرف چند امراء خاندان ہی ایسے تھے جن کو طائف سے غلہ آتا تھا.باقی لوگوں کے لئے یا تو یمن سے غلہ آتا تھا یا مدینہ اور اس کے نواحی سے آتا تھا بلکہ بعض دفعہ شام سے بھی لانا پڑتا تھا.زیادہ تر یمن سے ہی مکہ میں غلہ آتا تھا.اسی طرح کبھی کبھار حبشہ سے بھی آجاتا تھا.پس اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ میں اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ تمہارا جائے وقوع ایسا تھا کہ تمہیں معمولی روٹی بھی کھانے کے لئے میسر نہیں آسکتی تھی مگر ہم نے محض اپنے فضل سے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ تمہیں بافراغت کھانا میسر آگیا اور تم بھوک کی تکلیف سے بچ گئے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مِنَ الْـجُوْعِ نہیں فرمایا اگر مِنَ الْـجُوْعِ ہوتا تو اس کے معنے محض بھوک کے ہوتے مگر مِنْ جُوْعٍ کے یہ معنے ہیں کہ ایسی شدید بھوک جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی.اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اٰمَنَهُمْ مِنَ الْخَوْفِ نہیں فرمایا بلکہ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ فرمایا ہے.اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے صرف خوف دور نہیں کیا بلکہ ایسا شدید خوف دور کیا جس نے تمہاری بنیادوں کو ہلا دیا تھا.غرض تنوین چونکہ تعظیم کے لئے آتی ہے اس لئے مِنْ جُوْعٍ کے یہ معنے ہوں گے کہ ایسی بھوک جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی اور مِنْ خَوْفٍ کے یہ معنے ہوں گے کہ ایسا خطرناک خوف جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی.چنانچہ اصحاب الفیل کے واقعہ میں مَیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت عبدالمطلب نے ابرہہ سے صاف طو رپر کہہ دیا تھا کہ ہم میں تم سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں اگر یہ خدا کا گھر ہے تو وہ آپ اس کو بچاتا پھرے پھر ھذیل اور بنو کنانہ نے بھی متفقہ طور پر غور کرنے کے بعد اہل مکہ کو یہی مشورہ دیا تھا کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے تم ابرہہ اور اس کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دو تاکہ وہ جو چاہے کر لے.یہ کتنا بڑا خوف ہے کہ ایک قوم کی قوم ہتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہو گئی یہی حکمت ہے جس کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے یہاں مِنَ الْخَوْفِ نہیں بلکہ مِنْ خَوْفٍ فرمایا ہے یعنی میں نے ایک عظیم الشان خوف سے تم کو بچایا.لیکن جہاں تنوین تعظیم کے لئے آتی ہے وہاں عربی زبان میں تنوین تحقیر کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے.اگر اس استعمال کو مدّ ِنظر رکھا جائے تو پھر مِنْ جُوْعٍ کے
Page 468
یہ معنے ہوں گے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ بھوک اور مِنْ خَوْفٍ کے یہ معنے ہوں گے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ خوف.یعنی ہم نے اتنی فراوانی اور کثرت کے ساتھ رزق دیا کہ مکہ والے چھوٹی سے چھوٹی بھوک سے بھی نجات پا گئے.یہ خدا تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مکہ والوں کو ایک ایسی خطرناک جگہ رکھ کر جہاں روٹی کا کوئی سامان نہ تھا ہر فرد کے لئے روٹی مہیا کر دی.حقیقتاً اگر غور کیا جائے تو یہ بڑے بھاری انعام اور فضل کا ثبوت ہے کہ ایسے خطرناک مقام پر رکھ کر اس نے ہر ایک کو روٹی مہیا کی.ہر ایک کو بافراغت رزق دیا.یہاں تک کہ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ بھوک کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو گئے.اسی طرح اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ کے یہ معنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو ادنیٰ سے ادنیٰ خوف سے بھی نجات دی.یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کو اس نے حرم کی حدود میں داخل ہی نہیں ہونے دیا باہر ہی اس کا خاتمہ کر دیا.اگر وہ مکہ میں داخل ہو جاتا اور منجنیقوں سے پتھر برسانے لگتا تو کچھ نہ کچھ خوف اہلِ مکہ کو ضرور ہوتا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا تو روایات میں آتا ہے کہ ایک منجنیق کا پتھر خانۂ کعبہ کو بھی آلگا اور اس کا کچھ حصہ جل بھی گیا.بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اگر وہ اسی طرح ہوا تھا تو حجاج نے جب حملہ کیا اس وقت خانہ کعبہ کا کچھ حصہ کیوں جل گیا تھا اور کیوں اس پر پتھر بھی آلگا اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ اس کی نیت خانۂ کعبہ کو پتھر مارنے کی نہیں تھی اتفاقی طور پر وہ اسے آلگا تھا.دوسرے آگ فوراً بجھا دی گئی تھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا.بہرحال جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اصحاب الفیل کی تباہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بطور ارہاص تھی اور خانۂ کعبہ کی حفاظت اپنی ذات میں اتنی مقصود نہیں تھی جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مقصود تھی.یہی وجہ ہے کہ جس شان سے اس وقت نشان ظاہر ہوا اس شان کا نشان بعد میں ظاہر نہیں ہوا.بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس وقت اہل مکہ کو ادنیٰ سے ادنیٰ خوف سے بھی بچایا اور ابرہہ کو وہیں مار دیا.حضرت علیؓ کے متعلق ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے کہا وَاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ کے یہ معنے ہیں کہ خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی(تفسیر قرطبی زیر آیت ھذا).مگر یہ ایسی پھسپھسی بات ہے کہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا ہو.بعض اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہ روایت حضرت علیؓ کی طرف یوں ہی منسوب کر دی گئی ہے(تفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت ھذا) کہ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ کے یہ معنے ہیں کہ کہیں خلافت قریش میں سے نہ چلی جائے.اس پر ایک مؤرخ نے لطیفہ لکھا ہے کہ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ خلافت قریش میں سے نہیں جائے گی مگر آخر وہ چلی ہی گئی.اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے پاس سے باتیں بنا کر
Page 469
دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یہی بات اس روایت کے متعلق معلوم ہوتی ہے.بعضوں نے کہا ہے کہ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ میں اس قحط کی طرف اشارہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پڑا.احادیث میں آتا ہے کہ جب قریش مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا اور سخت تکالیف پہنچائیں تو آپؐ نے دعا فرمائی کہ اَللّٰھُمَّ خُذْھُمْ بِسِنِیْـنَ کَسِنِی یُوْسُفَ یعنی اے اللہ تو ان لوگوں کو ویسے ہی پکڑ جیسے یوسف کے زمانہ میں تو نے لوگوں کو قحط سے پکڑا تھا(تفسیر عبد الرزاق سورۃ حٰمٓ الدّخان).اس پر مکہ میں ایک شدید قحط پڑا.آخر وہی لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی.چنانچہ آپ نے دعا کی جس پر کچھ اردگرد کے علاقہ میں بارشیں ہو گئیں.کچھ حبشہ کی حکومت نے وہاں غلہ بھجوا دیا اور اس طرح قحط دور ہوا.پس بعض لوگ کہتے ہیں کہ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ میں اسی قحط کی طرف اشارہ ہے.مگر یہ درست نہیں.اس لئے کہ واقعات سے یہ ثابت ہے کہ یہ سورۃ نہایت ابتدائی سورتوں میں سے ہے اور وہ قحط جو مکہ میں پڑا وہ شعب ابی طالب میں محصور ہونے کے وقت پڑا.پس یہ آیت جب پہلے نازل ہو چکی تھی تو قحط کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہوا.یہاں تواللہ تعالیٰ ان پر حجّت کرتا ہے کہ اس نے ان کے خوف کو امن سے بدل دیا.جو چیز ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی تھی وہ ان کے لئے حجّت کس طرح ہو سکتی تھی.بہرحال اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کی طرف اشارہ ہے خالی سفروں کی طرف اشارہ نہیں.چنانچہ جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانۂ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی تو اس وقت آپ نے ایک دعا فرمائی تھی جس کا اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں ذکر فرماتا ہے.وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ(ابراھیم:۳۶).اسی طرح آپ نے یہ دعا کی تھی کہ رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ١ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ (ابراهيم :۳۸) حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تو اس گھر کو امن والا بنائیو اور مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچائیو.پھر کہتے ہیں اے خدا میں نے اپنی اولاد کو تیرے مکرم و محترم گھر کے پاس ایک ایسی جگہ لا کر بسا دیا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی محض اس لئے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں اور تیرے ذکر میں مشغول رہیں فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ.پس اے خدا تو خود لوگوں کے دلوں میں تحریک کر کہ وہ ان کی طرف جھکیں وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَاور انہیں کھانے کے لئے ہر قسم کے پھل عنایت فرما تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں.
Page 470
اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لئے دو باتیں مانگی ہیں.امن.۱ اور رزق.۲ اور پھر ذریعہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ امن اور رزق انہیں کس طرح ملے؟ آپ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں انہیں حکومت اور تلوار کے زور سے نہ ملیں.بے شک دنیا میں حکومت کے زور سے امن بھی قائم ہو جاتا ہے اور حکومت لوگوں کا روپیہ بھی کھینچ کھینچ کر لے آتی ہے مگر آپ فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ انہیں اس رنگ میں یہ چیزیں ملیں.میری دعا اور التجا یہ ہے کہ فَاجْعَلْ اَفْىِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو اور وہ عقیدت کے ساتھ ان کی طرف جھکیں.گویا جو کچھ ملے زور اور طاقت سے نہ ملے بلکہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے ملے.یہ کتنی کڑی شرطیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں لگا دی ہیں.یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص جنگل میں جا کر یہ دعا کرے کہ خدایا مجھ پر بارش برسا وہ میرے اردگرد نہ برسے.وہ صرف آدھ گھنٹہ برسے اور جب برس چکے تو فوراً اسی جگہ سے ایک درخت نکل آئے.حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو ایک جنگل میں لا کر بٹھا دیتے ہیں اورپھر دعا یہ کرتے ہیں کہ انہیں امن حاصل ہو.بھلا جنگل میں امن کہاں! جنگل میں تو یہی ہو سکتاہے کہ کوئی بھیڑیا آئے اور چیر پھاڑ جائے یا کوئی ڈاکو آئے اور وہ لوٹ لے.پھر وادیٔ غیر ذی زرع کہاں اور رزق کہاں! مگر وہ ایک جنگل میں اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا انہیں رزق عطا فرما.گویا اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی اولاد کے لئے دو چیزیں مانگتے ہیں.رزق بھی مانگتے ہیں اور امن بھی مانگتے ہیں اور مانگتے بھی وادیٔ غیر ذی زرع میں ہیں.مگر پھر یہیں پر بس نہیں کرتے بلکہ ایک اور شرط یہ عائد کرتے ہیں کہ انہیں رزق اور امن تو ملے مگر تلوار سے نہیں.حکومت اور طاقت کے زور سے نہیں بلکہ اس طرح کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور وہ خود بخود عقیدت مندانہ جذبات کے ساتھ ان کی طرف جھکتے چلے جائیں یہ کتنی سخت اور کڑی شرائط ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ساتھ لگائی ہیں.اس کے مقابلہ میں وہ دو۲ باتیں اپنی اولاد کی طرف سے بھی کہتے ہیں.ایک یہ کہ وہ مکہ میں رہیں گے اور دوسری یہ کہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں گے اور وہ عبادت توحید والی ہو گی.اللہ تعالیٰ اسی دعائے ابراہیمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ١ۙ۬ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.اے مکہ والو! ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا جو ہم نے ابراہیم کےساتھ کیا تھا.اب کیا تمہارا فرض نہیں کہ تم بھی اس عہد کو پورا کرو جو تمہاری طرف سے تمہارے دادا ابراہیمؑ نے کیا تھا.یہ دو باتیں کہ وہ مکہ میں رہیں گے اور عبادتِ خدا میں لگے رہیں گے اور عبادت بھی توحید والی کریں گے ہم نے نہیں کہی تھیں.ہم نے ابراہیمؑ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اے ابراہیم چونکہ تو ہم سے دو چیزیں مانگ رہا ہے ہم بھی تجھ سے دو چیزیں مانگتے ہیں.ہم نے
Page 471
ابراہیم سے کوئی سودا نہیں کیا.بلکہ ابراہیم نے خود کہا کہ اے میرے رب میں تجھ سے یہ سودا کرتا ہوں اور یہ سودا پیش کرنے والا تمہارا اپنا دادا تھا.اس کی بات کی پچ تو تمہیں زیادہ ہونی چاہیے.ہم پر ابراہیم نے جو ذمہ واری رکھی تھی وہ ہم نے پوری کر دی.الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ١ۙ۬ وَّ اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.اس نے جہاں کہا تھا ہم نے رزق پہنچایا اس نے کہا تھا کہ میری اولاد کو وادیٔ غیر ذی زرع میں رزق دیا جائے.سو ہم نے وادیٔ غیر ذی زرع میں ہی تمہیں رزق دے دیا.اس نے کہا تھا کہ انہیں اس خطرناک مقام پر امن دیا جائے.سو ہم نے اس خطرناک مقام پر تمہیں امن دے دیا.اس نے کہا تھا کہ یہ رزق اور امن انہیں تلوار کے زور سے نہ ملے بلکہ لوگوں کی محبت اور پیار کے نتیجہ میں ملے سو ہم نے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت قائم کر دی اور اب اسی محبت کے نتیجہ میں تمہیں رزق اور امن حاصل ہو رہا ہے.اب کیا تمہارا فرض نہیں کہ تمہارے دادا نے تمہاری طرف سے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ اس گھر میں ہمیشہ کے لئے بس جائیں گے اور اس میں خالص تیری عبادت کو قائم کریں گے، تم اسے پورا کرو.ہم نے کتنے عرصہ تک اپنے وعدہ کو پورا کیا.اس کے مقابلہ میں تمہاری طرف سے بھی یہ وعدہ تھا کہ ہم مکہ میں رہیں گے اور خدائے واحد کی پرستش بجا لائیں گے تم ہزاروں سال سے شرک کرتے چلے آرہے ہو مگر ہم نے تمہیں کچھ نہیں کہا.کیونکہ تم کہہ سکتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تعلیم نہیں پہنچی.لیکن اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھیج دیئے گئے ہیں اور وہ تمہیں خدائے واحد کی طرف بلا رہے ہیں.مگر اے ظالمو! تم اب بھی خدائے واحدکی طرف نہیں آرہے.
Page 472
سُوْرَۃُ الْمَاعُوْنِ مَکِّیَّۃٌ سورۃ الماعون.یہ سورۃ مکی ہے وَھِیَ سَبْعُ اٰیَاتٍ دُوْنَ الْبَسْمَلَۃِ وَفِیْـہَا رُکُوْعٌ وَّاحِدٌ اور اس کی بسم اللہ کے سوا سات آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے سورۃ ماعون مکی سورۃ ہے یہ سورۃ سورۂ ماعون کہلاتی ہے اکثرعلماء کے نزدیک یہ سورۃ مکی ہے.حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور قتادہ کے نزدیک مدنی ہے.ھبۃ اللہ جو قرآن کریم کے ایک بڑے مفسر گذرے ہیں ان کے نزدیک اس کا نصف مکی ہے اور نصف مدنی ہے.نصف مکی ان کے نزدیک عاص بن وائل کی نسبت اترا ہے اور نصف مدنی ان کے نزدیک عبداللہ بن ابی ابن سلول کی نسبت اترا ہے(زاد المسیر فی علم التفسیر سورۃالماعون ).مستشرقین میں سے نولڈکے اسے ابتدائی سالوں کی سورۃ قرار دیتا ہے اورمیور پانچویں سال کی قرار دیتا ہے(A Comprehensive Commentary on Quran vol:4 P:284) اور وہیری جسے شوق ہے کہ وہ کوئی بڑا محقق سمجھا جائے اور کوئی نئی بات پیش کرے یا نئی بات کی تائید کرے اس نے کہا ہے کہ میری رائے بھی ھبۃ اللہ کے مطابق ہے کہ یہ سورۃ آدھی مکی ہے اورآدھی مدنی ہے.چونکہ اکثر مفسرین اور راوی اسے مکی قرار دیتے ہیں اس لئے کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کی نسبت کوئی اور تحقیقات پیش کریں.بے شک حضرت ابن عباسؓ جو صحابی ہیں ان کی روایت یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنی ہے.لیکن حضرت ابن عباسؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ت کے وقت کوئی تیرہ سال کے تھے اس لئے وہ جو کچھ بیان فرماتے ہیں اس میں سےننانوے فی صدی دوسروں سے سنا ہوتاہے جس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتاہے.یوں بوجہ بہت زیرک ہونے کے اکثر اوقات ان کی رائے درست اور صحیح ہوتی ہے.زمانۂ نزول کےمتعلق بعض دفعہ صحابہ اور تابعین نے اس امر سے بھی دھوکا کھایا ہے کہ اگر کسی آیت کے بارہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے یہ کہہ دیا کہ یہ فلاں شخص کے بارہ میں نازل ہوئی تھی اگر وہ شخص مکی تھا تو انہوں نے قیاس کر لیا کہ وہ آیت یا سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اگر کسی مدینہ کے شخص کے بارہ میں روایت میں ایسے الفاظ آئے تو انہوںنے سمجھ لیا کہ وہ آیت یا سورۃ مدنی ہے.پس اس سورۃ کے مضمون کو دیکھتے
Page 473
ہوئے میرے نزدیک قرین قیاس یہی ہے کہ اَئمۂ جمہور نے جو سمجھا وہی درست تھا.گو جمہور نے اپنی تائید میں کوئی ایسی روایت جو کسی صحابی سے مروی ہو نہیں لکھی.لیکن اکثر تابعین کا اس پر اتفاق بتاتا ہے کہ روایات تو ضرور تھیں مگر بوجہ شہرت عامہ کے انہوں نے ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی.شان نزول بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ سورۃ ابوجہل کے متعلق اتری ہے.دوسرے لکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے متعلق اتری ہے.بعض کہتے ہیں کہ عاص بن وائل کے متعلق اتری ہے.یا عمرو بن عائذ کے متعلق اتری ہے یا مدینہ کے دو منافقوں کے متعلق اتری ہے یا ابوسفیان بن حرب کے متعلق اتری ہے(فتح البیان سورۃ الماعون ابتدائیۃ).اس قسم کی روایات کو بیان کرنے کی میرے لئے کوئی ضرورت نہیں تھی.میںنے انہیں صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ یہ ایک واضح مثال اس بات کی ہے کہ بعض دفعہ مختلف آراء کے ملنے سے کس طرح ایک مضحکہ خیز بات بن جاتی ہے.بھلا جس چیز کے متعلق کوئی یقینی پتہ ہی نہیں اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت کیا تھی یہ بات کہ کوئی آیت یا سورۃ کس شخص کے بارہ میں ہے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون بتا سکتا تھا اور اگر آپ بتاتے کہ یہ آیت کس شخص کےبارہ میں اتری ہے تو آپ ایک شخص کا نام لیتے یا ایک جماعت کے ایک فعل کا ذکر کرتے.یہ تو نہیں کہ آپ فرماتے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ آیت یا سورۃ فلاں شخص کے بارہ میں ہے یا فلاں کے یا فلاں کے.اس قسم کے شبہ والی بات یا غیریقینی رائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت قرآنی کی نسبت جس کا علم آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا تھا کس طرح کہہ سکتے تھے.پس یہ روایات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں بلکہ لوگوں کےخیالات ہیں اور لوگوں کےخیالات سے شانِ نزول کا پتہ نہیں لگ سکتا.میں نے اس آیت کے شان نزول کی نسبت مختلف روایات کے مطابق صرف سات آدمیوں کانام لیا ہے ورنہ روایات میں بارہ کے قریب لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی مراد ہے.پس ان روایات کی طرف تفسیر میں اشارہ کرنا اس آیت کی تفسیر کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے بالکل غیر ضروری تھا مگر اس آیت کے بارہ میں جو یہ روایات آئی ہیں ان کی ایک قیمت ضرور ہے اور وہ یہ کہ ان سے خوب اچھی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ شانِ نزول کے معنے یہ نہیں ہوتے کہ واقعہ میں اس شخص یا واقعہ کے بارہ میں وہ آیت نازل ہوئی ہے.بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا مضمون فلاں شخص یا واقعہ پر بھی چسپاں ہوتا ہے.اگر یہ مطلب ان روایات کا نہیں ہوتا تو پھر یہ روایات جو اس آیت کو بارہ متفرق اشخاص کے بارہ میں بتاتی ہیں ایک دوسرے کے نقیض ہونے کے سبب سے جھوٹی کہلائیں گی اور ان کے راوی خواہ صحابی ہوں خواہ تابعی نعوذ باللہ من ذالک مفتری قرار پائیں گے.مگر چونکہ ان لوگوں کی دیانت اور راستبازی کو
Page 474
دیکھتے ہوئے ان کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا اس لئے سوائے اس توجیہ کے اور کوئی توجیہ ان روایات کی ہو ہی نہیں سکتی کہ ان لوگوں کا یہ منشا نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ یہ آیت فلاں شخص کی نسبت ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ ہمارے علم میں فلاں شخص کے حالات پر یہ آیت خوب چسپاں ہوتی ہے.پس شانِ نزول کی کسی روایت سے کسی آیت کے معنوں کو ایک خاص واقعہ سے محدود کرنا نہایت غلط طریق ہے اور قرآن کریم کے وسیع سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنے کی ناکام کوشش کے مترادف ہے.اس زمانہ کے مسلمان علماء میں یہ عام مرض ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی جائے اور انہیں کہا جائے کہ اس سے یہ مضمون نکلتا ہے تو وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ واہ ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ اس کا تو شانِ نزول یہ ہے اور یہ آیت فلاں شخص سے تعلق رکھتی ہے.گویا جس طرح کشتی کو کسی کیلے یا درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے وہ اس آیت یا سورۃ کو کسی منافق یا مومن یا مہاجر یا انصاری یا عیسائی یا یہودی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں.حالانکہ قرآن کریم کسی خاص شخص کے لئے نہیں آیا بلکہ ساری دنیا کے لئے آیا ہے اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہیں اور تمام مسلمان اور عیسائی اور یہودی اور مجوسی وغیرہ بھی مخاطب ہیں.پھر قیامت تک آنے والے تمام لوگ بھی اس کے مخاطب ہیں.زید یا بکر کے ساتھ اس کی کسی آیت یا سورۃ کو مخصوص قرار دینا قطعی طور پر غلط بات ہے.بلکہ میں تو اس بات کو بھی جائز نہیں سمجھتا کہ قرآن کریم کو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص قرار دیا جائے.اگر قرآن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی بات کہتا تو وہ وہیں ختم ہو جاتی اور باقی دنیا اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتی.حالانکہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ہے.مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ.اب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو اصحاب الفیل کے واقعہ پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ پس میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کسی سورۃ یا آیت کے شانِ نزول کو مخصوص قرار دینا جائز نہیں سمجھتا کجا یہ کہ یہ قرار دیا جائے کہ کوئی سورۃ یا آیت کسی منافق یا کسی مومن یا کسی کافر کے متعلق نازل ہوئی ہے.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا ہے مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ قرآن ہمارے لئے نازل نہیں ہوا.جیسے ان پر نازل ہوا ہے ویسے ہی ہمارے لئے نازل ہوا ہے.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم پر فضیلت حاصل ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیکی اور آپ کے تقویٰ اور آپ کے عرفان اور آپ کی روحانیت کے اعلیٰ مقام کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس غرض کے لئے چن لیا کہ
Page 475
آپ پر اپنا کلام نازل کرے اور آپ کو اس کا پہلا مخاطب قرار دے.پس آپ کی جو روحانی اور اخلاقی اور دماغی فضیلت تھی اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اپنا کلام آپ پر پہلی دفعہ نازل کیا.لیکن جب وہ نازل ہو گیا تو اس کے بعد میرے لئے، اس تفسیر کے پڑھنے والوں کے لئے اور باقی سب دنیا کے لئے وہ ویسا ہی ہو گیا جیسے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا.اس شانِ نزول کے مخمصہ سے تنگ آکر رازی اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شانِ نزول کیا ہے بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ آیت کا مطلب کیا ہے(تفسیر کبیر لامام رازی زیر آیت اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ) مگر میں کہتا ہوں کہ جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے خود شانِ نزول کے معنے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی ہے ورنہ ان الفاظ کے اور معنے ہیں اور ان کے رو سے آیت کا مفہوم محدود ہوتا ہی نہیں.اب میں ان روایات کے مضمون کو لیتا ہوں بعض راوی کہتے ہیں ابوجہل نے اور بعض کہتے ہیں عاص بن وائل نے ایک اونٹ ذبح کیا تو ایک یتیم کچھ گوشت مانگنے کے لئے آگیا.اس پر اس نے یتیم کو سونٹا مارا.آخر اونٹ اس نے خود تو نہیں کھانا تھا بہرحال اس کا گوشت اس نے تقسیم ہی کرنا تھا مگر اس نے تقسیم ان لوگوں میں کرنا تھا جن میں تقسیم کرنے میں اس کی شہرت اور عزت میں زیادتی ہو.پس جب وہ یتیم گوشت مانگنے کے لئے آیا تو وہ اسے خفا ہوا اور غصہ سے اس کو سونٹا مارا.دوسری روایات میں جہاں اشخاص کے نام بدلے ہیں اعمال میں بھی اختلاف ہے جو ان سے ظاہر ہوئے.مگر مفہوم ان سب روایات کا یہی ہے کہ ان لوگوں نے کسی نہ کسی طرح یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا تھا.پس سب روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ اس آیت کا مضمون ابوجہل پر بھی چسپاں ہوتا ہے، ولید بن مغیرہ پر بھی چسپاں ہوتا ہے، عاص بن وائل پر بھی چسپاں ہوتا ہے، عمر بن عائذ پر بھی چسپاں ہوتا ہے، مدینہ کے دو منافقوں پر بھی چسپاں ہوتا ہے، ابوسفیان بن حرب پر بھی چسپاں ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب لوگ بوجہ دینِ محمدی کی روح سے دور ہونے کے بخیل اور ظالم تھے اور اگر اوپر کی تشریح کے مطابق ان روایات کا مطلب سمجھا جائے تو یہ روایات بالکل درست ہیں.بلکہ دس یا بارہ کی بھی شرط نہیں یہ مضمون تو لاکھوں پر چسپاں ہو سکتا ہے.اس زمانہ کو ہی دیکھ لو دنیا کی دو ارب آبادی میں سے اگر وہ لوگ تلاش کئے جائیں جو تکذیب دین کرنے والے ہیں تو ایک ارب سے زیادہ ایسے لوگ نکل آئیں گے جو علی الاعلان دین کا انکار کرتے ہیں.پھر ساٹھ ستّر کروڑ ایسے لوگ نکل آئیں گے جو منہ سے تودین کا انکار نہیں کرتے مگر شامل وہ پہلے گروہ میں ہی ہیں.باقی تیس کروڑ میں سے انتیس کروڑ سے بھی اوپر وہ لوگ نکلیں گے جو یوں تو انکار نہیں کرتے مگر عملاً وہ بھی دین کا انکار کرتے ہیں.صحیح معنوں میں دین کو ماننے والا اور سچے دل سے
Page 476
اس پر ایمان رکھنے والا بہت تھوڑا حصہ نکلے گا جو ہزاروں یا زیادہ سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گا.پس ہم کہہ سکتےہیں کہ ان ساروں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر ان کے لئے نازل نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو مجرم کس طرح قرار دے گا پھر تو وہ بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ یہ آیت ہمارے متعلق نہیں بلکہ فلاں شخص کے متعلق تھی.یہ لوگ موردِ الزام اسی صورت میں سمجھے جا سکتے ہیں جب یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ آیت کسی خاص شخص سے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص جو تکذیبِ دین کرتا ہے وہ اس کا مخاطب ہے.جن مفسرین نے اس آیت کو ابوجہل پر چسپاں کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک یتیم کا مال ابوجہل کے سپرد تھا ایک دن وہ ننگا دھڑنگا اس کے پاس آیا.کپڑے اس کے پاس نہیں تھے اور اس نے آکر تقاضا کیا کہ میری امانت میں سے کچھ روپیہ مجھے دے دیا جائے مگر ابوجہل نے اسے دھتکارا اور وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا.قریش کے رؤوسا نے اسے شرارتاً مشورہ دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے سفارش کراؤ وہ غریبوں کی خدمت کابڑا دعویٰ کیا کرتے ہیں.ان کی غرض یہ تھی کہ آپ سفارش کریں گے تو ابوجہل آپ کو ڈانٹے گا اور آپ ذلیل ہوں گے اور سارے شہر میں آپ پر ہنسی اڑے گی.اور اگر سفارش نہیں کریں گے تب بھی آپ کی سُبکی ہو گی.ہم ہر جگہ لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو غریبوں کی مدد کرنے کے بڑے بڑے دعوے کئے جاتے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ ایک یتیم سفارش کے لئے آیا اور ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کی سفارش ہی کر دیں.بہرحال قریش کے مشورہ پر وہ آپ کے پاس گیا.جب وہ یتیم آپ کے پاس پہنچا تو چونکہ آپ نے حلف الفضول میں عہد کیا ہوا تھا کہ آپ غرباء کی مدد کیا کریں گے اس لئے آپ فوراً اس کے ساتھ چلنے کے لئے کھڑے ہو گئے.آپ نے یہ بھی نہ سوچا کہ کس دشمن کے پاس جارہے ہیں اسے ساتھ لیا ابوجہل کے دروازہ پر پہنچے اور دستک دی ابوجہل باہر آیا تو آپ نے فرمایا یہ یتیم آیا ہے اس کی کچھ امانت آپ کے پاس ہے چونکہ اسے روپیہ کی ضرورت ہے اس لئے آپ وہ روپیہ اسے دے دیں.ابوجہل چپ کر کے اندر گیا اور اس نے روپیہ لا کر اس یتیم کو دے دیا.جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ابوجہل کو طعنے دیئے اور کہا کہ تو تُو صبائی ہو گیا ہے قریش مکہ میں مسلمانوں کو صبائی یا صابی کہا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صابی ایک فرقہ تھا جو عراق میں رہتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہوتا تھا.یہ لوگ چونکہ حضرت ابراہیمؑ کا بہت ذکر کیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دین کو دینِ حنیفی کہتے تھے.مکہ کے لوگوں نے اس مشابہت کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی صابی یا صبائی کہنا شروع کر دیا.غرض جب ابوجہل نے اس یتیم کو مال واپس کیا تو قریش نے اسے طعنے دیئے اور کہا کہ تو تُو صبائی ہو گیا ہے.اس نے کہا خدا کی قسم میں
Page 477
صبائی نہیں ہوا.لیکن جب میرے سامنے محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں اور بائیں وحشی اونٹ کھڑے ہیں اور میں ڈرا کہ اگر میں نے آپ کی بات نہ مانی تو یہ اونٹ مجھ پر حملہ کردیں گے.یہ روایت ایک اور طرح بھی آتی ہے اور میرے نزدیک وہی زیادہ صحیح ہے کہتے ہیں کہ مکہ میں جب حلف الفضول کا معاہدہ ہوا یعنی تین فضل نامی شخصوں نے ایک انجمن بنائی کہ اس کے سب ممبر قسم کھائیں کہ مظلوم کی مدد کریں گے (میں نے بھی اس کی نقل میں ایک تحریک جاری کی تھی مگر افسوس کہ وہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکی جب خدا تعالیٰ چاہے گا کامیاب ہو جائے گی یہ تحریک ایک رؤیا کی بناء پر تھی.میں نے دیکھا کہ گویا خدا تعالیٰ کا ارشاد ہو اہے کہ تم اپنے خاندان کے لوگوں سے کہہ دو کہ اگر حلف الفضول پر ان کا عمل رہے تو وہ تباہی سے بچے رہیں گے) اس معاہدہ کے بعد وہ نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچے.یہ دعویٰ سے پہلے کی بات ہے.آپ نے بھی غرباء کی مدد کرنے کی قسم کھائی اور اس معاہدہ میں شامل ہو گئے.مگر کچھ عرصہ کے بعدوہ نوجوان اس معاہدہ کو بھول گئے.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے آدمی تھے.آپ کو یہ معاہدہ یاد رہا.جب آپ نے دعویٰ کیا تو ایک دن بعض مخالفوں نے شرارتاً یہ چاہا کہ آپ کا امتحان لیا جائے.انہوں نے سوچا کہ آپ نے بھی غریبوں کی حمایت کے لئے قسم کھائی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ غریبوں کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں.روایات میں آتا ہے کہ ایک بدوی تھا جس سے ابوجہل نے کچھ سامان لیا تھا مگر اس کی رقم اسے نہ دی تھی.وہ بدوی مکہ میں آتا اور شور مچاتا کہ ہم باہر سے آتے ہیں اپنا سودا یہاں فروخت کرتے ہیں مگر مکہ کے یہ لوگ جو بیت اللہ کے محافظ اور مذہبی آدمی سمجھے جاتے ہیں ہم پر اس اس رنگ میں ظلم کرتے ہیں اور جب لوگ اس سے دریافت کرتے کہ کیا ہوا تو وہ کہتا کہ ابوجہل نے میری اتنی رقم دینی ہے مگر وہ نہیں دیتا.وہ کچھ فاتر العقل سا تھا اور یوں اس کا نقصان بھی کافی ہوا تھا جب وہ اس طرح بار بار شور مچاتا تو ایک دن لوگوں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ اسے محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس بھیج د و اور اسے کہا کہ وہ آپ کو ساتھ لے جائے.ان کی نیت نیک نہیں تھی ان کا منشا صرف یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نہ گئے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو آپ نے غریبوں کی مدد کے لئے قسم کھائی ہوئی تھی مگر اس کو پورا نہ کیا اور اگر گئے تو چونکہ ابوجہل آپ کی بات نہیں مانے گا آپ ذلیل ہوں گے.بہرحال انہوںنے اس بدوی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا.جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو آپ نے اسی وقت اپنی چادر سنبھالی اور اس بدوی کے ساتھ چل پڑے.ابوجہل کے دروازہ پر پہنچ کر آپ نے دستک دی.جب وہ باہر آیا تو آپ نے فرمایا اس بدوی کی کچھ رقم آپ نے دینی ہے اسے روپیہ کی سخت ضرورت ہے.میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں
Page 478
کہ آپ اس کی رقم اسے دے دیں.اس نے کہا اچھا میں ابھی لاتا ہوں.چنانچہ وہ اندر گیا اور روپیہ لا کر اس نے بدوی کو دے دیا.جب اس کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اسے طعنہ دیا کہ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ ان کا مال کھانا جائز ہے (جیسے آج کل بعض مولوی کہتے ہیں کہ احمدیوں کا مال لوٹ لینا اور اسے کھاجانا جائز ہے) مگر تمہاری اپنی یہ حالت ہے کہ روپیہ فوراً لا کر دے دیا.تم نے یہ کیا کیا.ہم نے تو اس کو ذلیل کرنے کے لئے یہ منصوبہ کیا تھا مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الٹاہم ذلیل ہو گئے.جب دوستوں نے اسے یہ طعنہ دیا تو روایتوں میں آتا ہے ابوجہل نے انہیں یہ جواب دیا کہ خدا کی قسم جب محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) میرے پاس آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے دائیں اور بائیں دو مست اونٹ کھڑے ہیں اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ اگر میں نے انکار کیا تو یہ دونوں اونٹ مجھ پر حملہ کر دیں گے.اس لئے میں ڈرا اور میں نے روپیہ لاکر دے دیا.بہرحال یہ ایک تاریخی واقعہ ہے.اب خواہ یہ سمجھ لو کہ ایک یتیم آپ کے پاس سفارش کے لئے آیا اور آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور خواہ اس واقعہ کو درست تسلیم کر لو کہ ایک بدوی آپ کے پاس آیا اور آپ اس کی رقم دلوانے کے لئے ابوجہل کے پاس گئے.ان دونوں میں سے کوئی بات سمجھ لو تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوجہل کے پاس گئے اور آپ نے ایک غریب کا کھایا ہوا مال اس سے اگلوا دیا.مذکورہ بالا معاہدہ کے بارہ میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا جاہلیت کی کوئی بات ایسی ہے جسے آپ پسند فرماتے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں حلف الفضول ایک ایسی چیز تھی کہ آج میں اسے اسلام میں بھی پسند کرتا ہوں.پھر آپ نے فرمایا لَوْ دُعِیْتُ الْاٰنَ لَاَجَبْتُ(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام حلف الفضول).اگر اب بھی میں اس کی طرف بلایا جاؤں تو میں اس میں ضرور حصہ لوں.مظلوم کی مدد کرنا ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے مگر افسوس کہ مسلمانوں میں سے اب یہ بالکل مٹ گئی ہے.وہ یوں تو بڑے جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں مگر غریبوں کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے.لوگ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں اور جس کا لحاظ ہوتا ہے اس کی طرف داری کرتے ہیں حالانکہ اصل تقویٰ یہ ہے کہ جس کا حق مارا جارہا ہو اس کی تائید کے لئے انسان کھڑا ہو جائے اور اس کا حق دلوانے کے لئے دوسرے کے دروازہ پر دھرنا مار کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تب تک نہیں ہلوں گا جب تک اس کا حق اسے نہ دلوا لوں.ترتیب سورۃ یہ سورۃ دراصل پہلی سورۃ کے مضمون کا تتمہ ہے.پہلی سورۃ میں یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے لئے رز ق مہیا کر دیا ہے تاکہ تم خدا تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اس کی عبادت کرو مگر تم اس طرف سے غافل ہو.اب یہ بتاتا ہے کہ جن قوموں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے بڑھتے بڑھتے ان کی یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ
Page 479
دنیا کی محبت موت کو بھلا دیتی ہے اور اُخروی زندگی پر سے ان کا ایمان بالکل اٹھ جاتا ہے.یہی مکہ کے لوگوں کا حال ہو گیا ہے ورنہ ابراہیمؑ کی اولاد اور قیامت کی منکر! یہ تعجب کی بات نہیں تو اور کیا ہے.خدا کا ایک اولوالعزم نبی جو ایک لمبی بنیاد دین کی قائم کرنا چاہتا ہے جس کی تعلیم اورجس کے نصائح کی بنیاد ہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کے قرب پر ہے اسی کی اولاد اگر اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ یہ جہان میٹھا ہے اگلے جہان کو کس نے دیکھا ہے.تو یہ کتنے غضب کی بات ہے.اتنا عظیم الشان تغیر یقیناً اس وقت تک نفس میں پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کوئی بڑی بھاری خرابی پیدا نہ ہوجائے.اور پھر میرے لئے جو بات نہایت تعجب انگیز ہے وہ یہ ہے کہ آل ابراہیم کے دونوں حصے اس وقت بعث بعد الموت کے منکر ہو گئے تھے.آل ابراہیم بنو اسحاق اور بنواسماعیل پر مشتمل ہے.ان میں سے بنو اسماعیل جو مکہ والے تھے وہ تو موت کے بعد کسی زندگی کے قائل ہی نہیں تھے.رہ گئے بنواسحاق، ان کے متعلق شاید یہ بات ہرایک کو معلوم نہ ہو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ بنو اسحاق کی کتابوں میں بھی کلی طور پر بعث بعد الموت کا ذکر اڑا دیا گیا تھا.عام طور پر مسلمان واعظ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کےنزدیک بھی قیامت کا دن آنے والا ہے.حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہودی کتابوں میں قیامت کا کوئی ذکر نہیں.اگر تم میں سے کسی نے بائیبل پڑھی ہو تو وہ میری اس بات کی صداقت کی گواہی دے سکتا ہے اور اگر کسی نے پہلے نہ پڑھی ہو تو وہ اب پڑھ کر دیکھ لے بلکہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں یوں ہی دس پندرہ صفحے کسی جگہ سے بائیبل کے الٹ لو اور دس پندرہ صفحے کسی جگہ سے قرآن کریم کے نکال لو اور پھر یہ دیکھو کہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ حیات بعد الموت کا ذکر آتا ہے اور بائیبل میں کتنی دفعہ حیات بعد الموت کا ذکر آتا ہے.تمہیں صاف دکھائی دے گا کہ قرآن کریم میں تو دس پندرہ صفحات میں ہی کئی جگہ مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر آجائے گا.مگر بائیبل میں اس سے دگنے صفحات میں بھی اس زندگی کی طرف اشارہ تک نہ ہو گا.حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بعد الموت زندگی کا ذکر یہودیوں میں سے بالکل مٹ گیا تھا.اب یہ تو ہم نہیں مان سکتے کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام نے انہیں حیات بعد الموت کی کوئی خبر نہیں دی تھی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو پے در پے انبیاء ان میں آئے جیسے داؤد، سلیمان، الیاس، زکریا، یحییٰ علیہم السلام ان میں سے کسی نے بھی ان سے حیات بعد الموت کا ذکر نہیں کیا.پس بائیبل میں اس کا کوئی ذکر نہ ہونا بتاتا ہے کہ یہود نے ایسی باتوں کو بائبل سے نکال دیا تھا.ساری بائیبل میں اس اہم مسئلہ کی طرف اشارہ تک نہ ہونا جبکہ قرآن کریم بعث بعد الموت کے ذکر سے بھرا پڑا ہے کوئی معمولی بات نہیں.میری رائے یہ ہے کہ بائبل میں یہ تغیّر اس لئے پیدا ہوا کہ یہود نے بائبل کی ان آیات کو جو اخروی زندگی کے متعلق تھیں غلطی سے اس جہان پر چسپاں کر لیا
Page 480
اور جب بعض حصے بائبل کے اس خیال کے خلاف روشنی ڈالتے نظر آئے تو انہوں نے ایسے حصوں کو بائبل سے نکال دیا جیسے قرآن کریم میں یہ بتایا گیا تھا کہ وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ(الرَّحْـمٰن: ۴۷) جو شخص خدا سے ڈرے گا اسے دو جنت ملیں گے اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی.تو مسلمانوں نے چونکہ سارا زور اُخروی جنت پر دے دیا تھا انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دونوں جنتیں اگلے جہان میں ملیں گی.اسی طرح جب یہودیوں نے اپنی کتاب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کےساتھ مختلف انعامات کا وعدہ کیا ہوا ہے تو چونکہ توجہ تمام تر دنیوی انعامات کی طرف تھی انہوں نے غلوّ کر کے یہ ساری باتیں دنیا کے متعلق سمجھ لیں اور جن حصوںکواس خیال کے مطابق کرنے میں دقّت محسوس ہوئی ان حصوں کو بائبل سے بالکل نکال دیا.قرآن کریم میں بھی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو اس جہان کے متعلق ہیں لیکن مسلمانوں نے ان کو اگلے جہان پر چسپاں کر دیا ہے.آخری پارہ میں بہت سی پیشگوئیاں ایسی ہیں جو اس زمانہ میں لفظاً لفظاً چسپاں ہوتی ہیں.جب انسان ایک طرف قرآن کریم میں ان پیشگوئیوں کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف ان واقعات کو دیکھتاہے جو دنیا میں رونما ہوئے تو اس کا دل عش عش کر اٹھتا ہے وہ بے اختیار سبحان اللہ کہنے لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اس کا یقین بہت بڑھ جاتا ہے مگر ہمارے مفسرین شروع سے لے کر آخر تک اس کو قیامت پر چسپاں کر دیتے ہیں.اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب کسی کو معلوم ہو کہ یہ سورۃ قیامت کے متعلق ہے تو وہ کہتا ہے چلو چھٹی ہوئی مجھے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے.مگر یہودی اس کے برخلاف بائبل کی سب باتیں جو اخروی زندگی کے متعلق تھیں ان کو اس جہان پر چسپاں کر دیتے تھے اگلے جہان کا ذکر ہمیشہ الہامی کتب میں استعارہ کی زبان میں کیا جاتا ہے.کہا جاتا ہے کہ وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں شراب کی نہریں ہوں گی اور دودھ سے مراد علم اور شراب سے مراد شرابِ محبت ہوتی ہے مگر وہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ اس دنیا میں ملے گا اس لئے اخروی زندگی کے متعلق جس قدر اشارے ان کی کتب میں پائے جاتے تھے وہ سب کے سب یا تو انہوں نے اس دنیا کے متعلق قرار دے دیئے تھے یا ان کو ناقابلِ تاویل دیکھ کر سرے سے اڑا ہی دیا تھا.ان اشارات کے مٹا دینے کی وجہ سے اب بائبل میں حیات بعد الموت کا کہیں ذکر ہی نظر نہیں آتا.غرض یہ ایک عجیب بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں نسلوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اُخروی زندگی کے ذکر کو اپنی کتب میں سے بالکل مٹا دیا تھا.عیسائیوں میں اُخروی زندگی کا کچھ خیال تو ضرور پایا جاتا ہے مگر عیسائیوں میں بھی اُخروی زندگی کا کوئی معیّن نشان نہیں.ہم سے کوئی پوچھے تو ہم جنت اور دوزخ کا حال اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کوئی شہر ہوتا ہے کیونکہ اسلام میں بڑی کثرت کے ساتھ
Page 481
ان باتوں ذکر آتا ہے.مگر عیسائیوں سے پوچھو تو ان کے ہاں اس کے متعلق عجیب قسم کا دوغلا سا خیال پایا جاتا ہے.مثلاً قیامت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَقُوْمُ السَّاعَۃُ عَلٰی اَشْـرَارِ النَّاسِ.یعنی دنیا میں جب صرف اشرار الناس رہ جائیں گے اور اخیار بالکل مٹ جائیں گے تو قیامت آجائے گی.اس کے یہ معنے نہیں کہ خدا تعالیٰ کی پیدائش بالکل فنا ہو جائے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا مٹ جائے گی اور اس کی جگہ کوئی اور دنیا قائم کردی جائے گی.لیکن عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نیکوں پر قیامت آئے گی.چنانچہ ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آخری زمانہ میں جب مسیح آئے گا تو شریر سب مار دیئے جائیں گے اور نیک ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی دنیا جنت بن جائے گی.گویا یہود نے بھی اس مادی دنیا کو اپنے لئے پسند کیا تھا اور عیسائیوں نے بھی اسی مادی دنیا کو جنت بنا لیا.جب وہ اس دنیا میں رہیں گے اور یہی دنیا جنت بن جائے گی تو اس کے معنے یہ ہیں کہ یہی بکرے کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، انہی بھینسوں کا دودھ پئیں گے اور یہی پھل اپنے استعمال میں لائیں گے قرآن کریم نے تو اس حقیقت کو پیش کیا تھا کہ جنت میں جو میوہ ملے گا اس کے کھانے سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے گی.اور جو دودھ کا پیالہ ملے گا اس کے پینے سے خدا تعالیٰ کا عرفان ترقی کرے گا.اور اس نے بتایا تھا کہ اس دنیا کی چیزیں جنت کی نعمتوں کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتیں.یہ چیزیں اور ہیں اور وہ چیزیں اور.مگر عیسائیوں کے نزدیک جب روحانی لوگ اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو یہی دنیا جنت بن جائے گی درحقیقت اس کے معنے یہ ہیں کہ اگر دنیا میں لوگ بھلے مانس بن جائیں، شرافت کے ساتھ اپنی زندگی کے دن بسر کرنے لگیں، شرارتوں اور بد اعمالیوں سے بچیں تو عیسائیوں کے نزدیک کسی اور جنت کی ضرورت ہی نہیں.اسی دنیا کو ہم جنت کہہ دیں گے.گویا وہ جنت جس میں ہمارے نزدیک انسان روحانی بنتے بنتے آخر خدا کو دیکھنے لگ جائے گا یہ تصوّر مسیحیوں کے نزدیک بالکل غلط ہے.ان کے نزدیک اس دنیا میں سے جب اشرار الناس کا خاتمہ ہو جائے گا تو یہی دنیا جنت کہلانے لگ جائے گی اور اسی دنیا کی نعمتیں ان کے لئے جنت کی نعمتیں بن جائیں گی.لیکن حال یہ ہے کہ مسیحی رُہبان موجودہ زمانہ کو پچھلے زمانوں سے برا اور خراب سمجھتے ہیں.مسلمانوں کی بھی آج کل یہی حالت ہے.وہ بھی جنت کو انہی مادی چیزوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں.مجھے یاد ہے ۱۹۱۲ء میں لکھنؤ میں ندوہ کا جلسہ ہوا مولوی شبلی صاحب مرحوم نے اس جلسہ کی صدارت کے لئے مصر سے علامہ رشید رضا بلوائے علامہ رشید رضا مفتی عبدہٗ کے شاگرد تھے اور مفتی عبدہٗ جمال الدین صاحب افغانی کے شاگرد تھے.جمال الدین صاحب افغانی کا طرز تفسیر ایک حد تک (گو اس درجہ کو نہیں پہنچ سکے) ہمارے ساتھ ملتا جلتا تھا.مفتی عبدہٗ ان کے شاگرد تھے اور مفتی عبدہٗ کے شاگرد علامہ رشید رضا تھے
Page 482
چونکہ مفتی عبدہٗ ایسی باتوں سے بچتے تھے جو خلافِ عقل اور نقل ہوں اور دشمن کو اسلام پر ہنسی کا موقع دیتی ہوں اس لئے ان کی تفسیر مصر میں بہت مقبول تھی.رشید رضا صاحب چونکہ ان کے شاگرد اور ان کے قدم پر چلنے والے تھے مصر میں ان کو بھی بہت رسوخ حاصل تھا گو مفتی عبدہٗ جیسا مقام ان کو حاصل نہیں تھا.بہرحال مولانا شبلی نے ان کو صدارت کے لئے بلوایا.یہ حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ عنہ کے زمانہ کی بات ہے.میں ان دنوں مدرسہ احمدیہ کا انچارج تھا.میں نے ارادہ کیا کہ بعض علماء کو اپنے ساتھ لے کر ہندوستان کے مشہور عربی مدارس کا دورہ کروں اور یہ دیکھوں کہ وہ مدارس کس رنگ میں جاری ہیں اور کس طرح ان میں لڑکوں کو تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اس تجربہ سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے مدرسہ کی تعلیم کو بھی ترقی دے سکیں.چنانچہ ہم اس دورہ کے سلسلہ میں دیوبند، فرنگی محل، رامپور اور بنارس وغیرہ گئے.دلّی کے مدارس بھی دیکھے.کان پور کے مدرسہ الٰہیات کا بھی معائنہ کیا.مولانا شبلی کو ہمارے اس دورہ کا پتہ لگا.تو چونکہ وہ مرنجانِ مرنج اور غیرمتعصب آدمی تھے آج کل کے ملّانوں کی طرح نہیں تھے انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے جلسہ پر ضرور تشریف لائیں اور ہمارے ہاں ہی قیام کریں.ہم ان کی دعوت پر چلے تو گئے مگر مصلحتاً ہم ان کے ہاں نہ ٹھہرے کیونکہ ہم نے سمجھا کہ غیراحمدیوں کو پتہ لگا تو وہ چڑیں گے اور ممکن ہے اس طرح کوئی بدمزگی پیدا ہو مگر جب مولانا شبلی کو پتہ لگا کہ ہم کہیں اور ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ اصرار کر کے ہمیں اپنے ہاں لے گئے اور ایک دو دن جب تک جلسہ ہوتا رہا ہم انہی کے ہاں ٹھہرے.ہمارے جانےسے کچھ بدمزگی بھی ہوئی اور غیر احمدیوں نے گالیاں بھی دیں مگر وہ ہمت والے آدمی تھے انہوں نے کوئی پروا نہ کی.اسی جلسہ میں ایک دن رات کے وقت ندوہ کے ایک پروفیسر عبدالکریم صاحب کی نماز کے موضوع پر تقریر رکھی گئی.اس جلسہ میں شہر کے بڑے بڑے رؤوسا، علماء اور اعلیٰ طبقہ کے لوگ خاص طور پر مدعو تھے.مجھے یاد نہیں کہ شبلی صاحب تھے یا نہیں بہرحال ہم سب لوگ موجود تھے کہ عبدالکریم صاحب ندوی نے نماز پر تقریر شروع کی.مولانا شبلی نے اس خیال سے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو نوجوان طبقہ کو خصوصیت سے مدعو کیا ہوا تھا اور بیرسٹر اور وکیل وغیرہ بڑی کثرت سے آئے ہوئے تھے بدقسمتی سے مولانا شبلی صاحب کو خود معلوم نہیں تھا کہ یہ پروفیسر صاحب کس لیاقت کے ہیں شاید وہ عربی اچھی پڑھاتے ہوں گے اس لئے شبلی صاحب کو ان پر حسن ظنی تھی بہرحال وہ تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک دو فقرے اس امر کے متعلق کہے کہ لوگوں کونماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے سے جنت ملتی ہے.مسلمانوں کے نزدیک جنت کا عجیب وغریب نقشہ اس کے بعد وہ نماز تو بھول گئے اور انہوں نے
Page 483
یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ جنت جو نماز کے بدلہ میں ملتی ہے کیا چیز ہے اور جنت کا جو نقشہ انہوں نے کھینچا وہ ایسا خطرناک تھا کہ میں سمجھتا ہوں چکلے میں بیٹھنے اور اس جنت میں بیٹھنے میں کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا تھا.انہوںنے بتایا کہ وہاں عورتوں کی اس اس طرح تصویریں لگی ہوئی ہوں گی اور جس تصویر کو انسان پسند کرے گا وہ اسی وقت عورت بن جائے گی اور وہ اس سے خلوت شروع کر دے گا.پھر وہ یوں کرے گا اس میں اتنی طاقتیں ہوں گی وہ فلاں فعل چوبیس چوبیس گھنٹہ تک کرتا چلا جائے گا.مجھے یاد ہے میرے ساتھ کچھ بیرسٹر بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ تقریر سن کر کہنے لگے خدا کا بڑا فضل ہے کہ یہ لیکچر رات کو ہوا اگر دن کو ہوتا اور غیرمسلم بھی اس میں آئے ہوئے ہوتے تو ہم شرمندگی سے ان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے.غرض مسلمانوں نے بھی جنت کو جو روحانیت کا مقام تھا، جو دیدار الٰہی کا مقام تھا ایک نہایت ہی شرمناک چیز بنالیا ہے.حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی دین کا انکار ہی ہے بھلا یہ بھی کوئی اقرار ہے کہ اس دنیا میں تو جہاں خدا تعالیٰ سے غافل کرنے کے ہزاروں سامان موجود ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر اور وہ جہان جہاں خدا نظر آجائے گا اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں عورتوں کی بغلوں میں ہم سارا دن گھسے رہیں گے نہ نماز ہو گی نہ عبادت ہو گی نہ عشقِ الٰہی کے جذبات ہوں گے نہ روحانیت کی ترقی کے کوئی سامان ہوں گے گویا اس دنیا میں ہمیں یوں کافر بنایا گیا اور جنت میں ہمیں اس طرح کافر بنایا جاتا ہے.بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۰۰۱ (میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں) اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِؕ۰۰۲ (اے مخاطب) کیا تو نے اس شخص کو پہچانا؟ جو دین کو جھٹلاتا ہے.حلّ لُغات.اَرَءَيْتَ.اَرَءَيْتَ کے لفظی معنے تو یہ ہیں کہ کیا تو نے دیکھا مگر عربی زبان میں رَءَیْتَ کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک رؤیتِ بصری کے معنوں میں دوم رؤیتِ قلبی کے معنوں میں یعنی اس کے معنوں میں آنکھ سے دیکھنا بھی شامل ہے اور دل سے دیکھنا بھی شامل ہے.مثلاً اس وقت میرے سامنے گھڑی پڑی
Page 484
ہوئی ہے اگر میں کسی سے کہنا چاہوں کہ میں نے اس گھڑی کو دیکھا تو میں کہوں گا رَءَیْتُ ہٰذِہِ السَّاعَۃَ(مفردات).لیکن کبھی یہ لفظ رؤیتِ قلبی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے.اس وقت اس کے معنے دیکھا کی بجائے ’’پایا‘‘ کے ہوتے ہیں.اردو میں بھی کہتے ہیں ’’میں نے اس کو ایسا پایا‘‘.چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں رَءَیْتُ زَیْدًا اَسَدًا میں نے زید کو شیر دیکھا اب اس کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ میں نے زید کو دیکھا تو شیر کی طرح اس کے پنجے تھے بلکہ معنے یہ ہوں گے کہ میںنے زید کا تجربہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑا بہادر انسان ہے.یہ رؤیتِ قلبی کہلاتی ہے کیونکہ تجربہ دل سے ہوتا ہے ظاہری آنکھ سے نہیں ہوتا.پس رَءَیْتُ زَیْدًا اَسَدًا کے یہ معنے نہیں کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے زید کو دیکھا تو وہ شیر نظر آیا بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ میں نے سرد اور گرم اور اچھی اور بری حالتوں میں اس کا تجربہ کیا اور میرے دل نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ ایسا ہے.رؤیتِ قلبی کے معنوں میں جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے دو مفعول آتے ہیں اور رؤیتِ بصری کی صورت میں صرف ایک مفعول آتا ہے.مگر جب اس سے پہلے ہمزہ آجائے تو اس وقت اس کے ایک اور معنے بھی ہو جاتے ہیں جو اس کی عام بناوٹ کے بالکل خلاف ہیں یعنی اس لفظ کے معنے پانے کے نہیں رہتے بلکہ یہ معنے ہو جاتے ہیں کہ اَخْبِـرْنِیْ مجھے بتاؤ.حالانکہ مفرد لفظ کے یہ معنے نہیں ہوتے ماضی کے صیغہ پر ہمزہ زائد کر دینے سے یہ معنے پیدا ہوتے ہیں.پس اَرَءَيْتَ.۱ کے لفظی معنے گو یہ ہیں کہ ’’کیا تو نے دیکھا‘‘.مگر عرب کے محاورہ کے مطابق اس کے معنے اَخْبِـرْنِیْ یعنی مجھے بتلاؤ کے ہو جاتے ہیں.اَلدِّیْن.اَلدِّیْنُ.دین کے عربی زبان میں تیرہ معنے ہیں (۱) اَلْـجَزَاءُ وَالْمُکَافَاۃُ.بدلہ اور مطابق عمل نتیجہ (۲) اَلطَّاعَۃُ.فرمانبرداری (۳) اَلْـحِسَابُ.حساب لینا (۴) اَلْقَھْرُ وَالْغَلَبَۃُ وَالْاِسْتِعْلَاءُ.کسی پر غلبہ پانا اور اس پر فائق ہو جانا (۵) اَلسُّلْطَانُ.بادشاہت اور حکومت (۶) اَلتَّدْبِیْـر.تدبیر (۷) مَا یُعْبَدُ بِہِ اللہِ.وہ حرکات و سکنات یا الفاظ جن کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے جس کو ہم نماز پڑھنا کہتے ہیں (۸) اَلْمِلَّۃُ.دین یا نظامِ جماعت (۹) اَلْوَرَعُ.بدیوں سے رکنے کی خواہش (۱۰) اَلْـحَالُ.حالت یا کیفیت (۱۱)اَلْقَضَاءُ.قضاء و قدر جسے تقدیر کہتے ہیں (۱۲) اَلْعَادَۃُ.عادت کا ہو جانا (۱۳) اَلشَّاْنُ.ایک خاص حالت (اقرب) شان کے معنے حالت کے ہوتے ہیں لیکن اَلشَّاْنُ کا لفظ عام حالت سے کسی قدر بلند معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے ہمارے ملک ۱ نوٹ: اَرَءَيْتَ کے محاورہ کے مطابق معنے اَخْبِرْنِیْ کے ہیں لیکن ہم نے ترجمہ کی سہولت کی غرض سے آیت کا لفظی ترجمہ کیا ہے کیونکہ بامحاورہ ترجمہ کریں توبعض الفاظ خطوط وجدانی میں لانے پڑتے ہیں اورخطوط کے باہر کا ترجمہ بے معنیٰ ہو جاتا ہے.
Page 485
میں بڑی شان کہہ دیتے ہیں یا اس کے معنے حالتِ مخصوصہ کے سمجھ لیں.اَرَءَيْتَ کے معنے اس جگہ تمام مفسرین اور نحویوں نے اَخْبِرْنِیْ کے کئے ہیں یعنی مجھے بتا.میں نے بتایا کہ جب یہ لفظ رؤیتِ قلبی کے معنوں میں استعمال ہو تو اس کے دو مفعول آیا کرتے ہیں.ایک مفعول تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ مجھے وہ شخص بتا جو تکذیبِ دین کرتا ہے.پس ایک مفعول تو آگیا سوال یہ ہے کہ دوسرا مفعول کہاں ہے؟سو ظاہر ہے کہ وہ مفعول یہاں محذوف ہے.حوفی نے جو ایک بڑے نحوی گذرے ہیں یہاں دوسرا مفعول اَلَیْسَ مُسْتَحِقًّا عَذَابَ اللہِ کے جملہ کو قرار دیا ہے یعنی مجھے بتا تو سہی کہ جو شخص دین کی تکذیب کرتا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق نہیں یعنی وہ عذاب کا مستحق ضرور ہے اور زمخشری نے وہ الفاظ مَنْ ھُوَ کے بتائے ہیں(البحر المحیط زیر آیت ھذا).زمخشری معتزلی ہے اور معتزلیوں کے خیالات آج کل کے نیچریوں سے ملتے جلتے تھے.لیکن ادب اور نحو میں وہ بڑے پایہ کےانسان ہیں ایک عربی لغت کی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے اور کم سے کم انہوں نے قرآن کریم کی یہ خدمت ضرور کی ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کی تائید میں عربی کے محاورات، نحو کے قواعد اور شعر بڑی کثرت سے لے آتے ہیں جس سے معنے بالکل واضح ہو جاتے ہیں.اور میرے نزدیک ان کی ایک یہ بھی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے بہت سی رطب و یابس باتوں سے اپنی تفسیر کو بالکل پاک کر دیا ہے گو اس کے ساتھ وہ ایک حد تک معجزات کا بھی انکار کر دیتے ہیں مگر جو لغو باتیں قرآن کریم کی طرف منسوب ہوتی تھیں ان سے بھی انہوں نے ایک حد تک تفسیر کو پاک کر دیا ہے.نیچری کی تلوار دو طرفہ چلتی ہے وہ لغویات بھی اڑا دیتا ہے اور ساتھ ہی کچھ سچے معجزے بھی اڑا دیتا ہے.علامہ زمخشری کے تجویز کردہ محذوف کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ مَنْ ھُوَ.یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اے مخاطبِ قرآن مجھے بتا تو سہی کہ وہ شخص جو دین کا انکار کرتا ہے وہ کون ہے.اس امر کی دلیل کہ اَرَءَيْتَ میں رؤیتِ بصری نہیں بلکہ قلبی ہے زمخشری نے یہ دی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں اس آیت کی ایک قرأت اَرَءَيْتَکَ ہے اور یہ مسلّمہ بات ہے کہ کافِ خطاب رؤیت بصری میں نہیں لگ سکتا(کشاف و بحر محیط زیر آیت ھذا).وہ اس قرأت سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں رؤیت بصری مراد نہیں ہو سکتی مگر میرے نزدیک اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی یہاں رؤیتِ قلبی ہی مراد ہو سکتی ہے بصری ہو ہی نہیں سکتی.حوفی کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں رؤیتِ بصری ہی مراد ہو اور حذف کوئی نہ ہو(بحر محیط زیر آیت ھذا)
Page 486
اور معنے یہ ہوں کہ کیا تو نے اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے دیکھا ہے اور مطلب یہ ہو کہ اس قسم کا انکار کرنے والے کو یقیناً تونے دیکھا ہے اور ہمزہ انکار کے لئے نہ ہو بلکہ اقرار کے لئے ہو جیسے اَلَمْ تَرَ میں نفی نہیں بلکہ اقرار ہے.مگر دراصل یہاں رؤیت بصری نہیں بلکہ رؤیتِ قلبی ہی ہے.کیونکہ مختلف اشخاص کو جب دیکھنے کا ذکر ہو تو اس وقت رؤیتِ بصری مراد نہیں ہو سکتی.آخر يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ سے کوئی ایک شخص تو مراد نہیں بلکہ سارا مکہ دین کی تکذیب کر رہا تھا.بلکہ سب دنیا ہی ایسا کر رہی تھی.اور جب ایک قوم کا ذکر ہو تو اس وقت رؤیتِ بصری نہیں بلکہ قلبی ہی مراد ہوسکتی ہے اور ایک وجود کے ذکر سے محض تشخّصِ ذہنی مراد ہوتا ہے ہم قوم کے فعل یا عمل یا طریقہ کا ایک وجود تسلیم کرکے کہتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آگیاہے.پس حوفی کے ان معنوں کو مدّ ِنظر رکھا جائے تب بھی دراصل رؤیتِ بصری نہیں بلکہ رؤیتِ قلبی ہی کا ذکر اس آیت میں پایا جاتا ہے.اس میں شبہ نہیں کہ ان معنوں کے رو سے مفعول ایک ہی سمجھا جائے گا لیکن مراد رؤیتِ قلبی ہی لی جائے گی.بہرحال یہ حوفی کا خیال ہے ان کے سوا سب علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس آیت میں رؤیتِ قلبی ہی مراد لی جا سکتی ہے.میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ قرآن کریم جو الفاظ استعمال کرتا ہے یامحاورے استعمال کرتا ہے ان کے جس قدر معنے ہوں وہ سب کے سب اگر سیاق و سباق کے لحاظ سے چسپاں ہو سکتے ہوں تو آیت کے صحیح معنے سمجھے جائیں گے.پس اَلدِّیْن کے جو معنے میں نے اوپر بیان کئے ہیں ان میں سے جو معنے بھی اس سورۃ کے مضمون کے مطابق ہوں ان کی طرف آیت کا اشارہ سمجھا جائے گا اور کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے کسی معنے کو ردّ کرے.پس میں ان مختلف معانی کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں.دین کے تیرہ معنے اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ (۱)مجھے بتا تو سہی کہ و ہ جو جزا سزا کا انکار کرتا ہے وہ کون ہے؟ (۲)یا مجھے بتا تو سہی کہ وہ جو اطاعت کا منکر ہے یعنی نظام یا اطاعت کا منکر ہے وہ کون ہے ؟ (۳)یا مجھے بتا تو سہی کہ وہ جو حق و انصاف کے غلبہ کا منکر ہےوہ کون ہے؟(۴)یا مجھے بتا تو سہی کہ حکومت الٰہیہ کا منکر کون ہے؟ (۵)یا مجھے بتا تو سہی کہ مذہب کا منکرکون ہے؟ (۶) یا مجھے بتا تو سہی کہ عبادت ِالٰہیہ کا منکر کون ہے؟ (۷)یا مجھے بتا تو سہی کہ قومی شیرازہ بندی یا دوسرے لفظوں میںمذہبی شیرازہ بندی کا منکر کون ہے؟ (۸)یا مجھے بتا تو سہی کہ شبہات سے محفوظ رہنےاور ان سے بچنے کی خواہش کا منکر کون ہے؟ (۹) یا مجھے بتا تو سہی کہ عادت کی طاقت اور اس کے اثرات کا منکر کون ہے؟ (۱۰)یا مجھے بتاؤ تو سہی کہ تدبیر صحیحہ کا منکر کون ہے؟ (۱۱)یا مجھے بتا تو سہی کہ قضاءِ الٰہی کا منکرکون ہے؟ (۱۲)یا مجھے بتا تو سہی کہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ آرائیوں اور اس کی جلوہ نمائیوں کامنکر کون ہے؟
Page 487
یہ بار۱۲ہ معنے سارے کے سارے اس جگہ پر چسپاں ہوتے ہیں.لغت کے بیان کردہ تیرہ معنوں میں سے بعض کو میں نے چھوڑ دیا ہے.مثلاً حال کے معنے میں نے چھوڑ دیئے ہیں کہ یہ لفظ شان کے لفظ سے بہت قریب معنے رکھتا ہے اور شان کے معنے میں نے لےلئے ہیں.مِلَّۃ کے معنوںکو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہےکیونکہ اس کے دو معنے ہیں اور دونوں اس جگہ چسپاں ہوتے ہیں.حساب کے معنوں کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہےاس لئے کہ حساب کے معنے جزا ومکافاۃ سے ملتے ہیں اور یہ معنے میں نے لئے ہیں پس ایک بڑھ گیا اور دو چھوڑ دیئے گئے.اوراس طرح تیرہ معنوں میں سے بارہ معنے رہ گئے.اب میں ان معنوں کے مطابق اس آیت کی تفسیر الگ الگ بیان کرتا ہوں.تفسیر.دِیْن کے پہلے معنوں کے لحاظ سےآیت کے یہ معنے تھے کہ مجھے بتا تو سہی کہ جزا و سزا کا منکر کون ہےیعنی اس کے فعل کی شناعت اور برائی بڑی وسیع ہے جیسے ہم کہتے ہیں بتاؤ تو سہی یہ بات کون کہتا ہے.اس کا یہ مطلب نہیں ہو تا کہ زید کہتا ہے یا بکر.بلکہ مطلب یہ ہو تا ہے کہ جوبھی کہتا ہے بڑی بری بات کہتا ہے.اسی مفہوم کے مطابق اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے بتا تو سہی کہ جزا و مکافاۃ کامنکر کون ہے یعنی وہ بہت برا آدمی ہے (آگے جا کر بتائے گا کہ جزا ومکافاۃ کے انکار کا نتیجہ کیا نکلے گا) یہ یاد رکھنا چا ہیے کہ یہ بارہ باتیں جو شمار کی گئی ہیں درحقیقت یہ اصولی بدیاں ہیں اور ان کے نتیجہ میں انسان ہزاروں ہزار جزئی بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.گویا ان میں سے ایک ایک بدی ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ قائم ہو جائے گی اس کے اندر اور ہزاروں بدیاں پیدا ہو جائیں گی مثلاً پہلی چیز جزا و سزا کا انکار ہے.جب بھی جزا وسزا کا منکر کوئی انسان ہو جائے گا اسے ہر قسم کی بدیوں پر دلیری پیدا ہو جائے گی.ہزارو ہزار نیکیاں انسان ڈر کے مارے کرتا ہے اور ہزاروں ہزار نیکیاں انسان امید کے ساتھ کرتا ہے.جزا و سزا سے مراد اخروی جزا و سزا ہی نہیں بلکہ جزا و سزا کا سلسلہ اس دنیا میں بھی چلتا ہے اور قرآن کریم میں متواتر بیسیوں جگہ پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگلے جہان سے ہی جزا و سزا شروع نہیں ہو تی بلکہ اسی جگہ سے شروع ہو جاتی ہے.انبیاء کے منکروں پر جو عذاب آتا ہے یا قانون قدرت کو توڑنے والوں کو جو سزائیں ملتی ہیں وہ اگلے جہان سے شروع نہیں ہوتیںبلکہ اسی جہان سے شروع ہو جاتی ہیں.پس اس جگہ یہ مراد نہیں کہ جو جنت و دوزخ کا قائل نہیں بلکہ مراد اعمال کا بدلہ ہے خواہ اس دنیا میں ملے خواہ اگلے جہان میں.ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنت و دوزخ کے قائل نہیں لیکن جزا وسزا کے قائل ہیں وہ بھی ہزاروں بدیوں سے بچے رہتے ہیں.مثلاً بعض لوگ ایسے ہیں جو قومی خرابیوں کے نتائج کے قائل ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ بعض قسم کے کیریکٹر پیدا ہوجائیں تو قوم تباہ ہوجاتی ہے اور بعض قسم کے کیریکٹر پیدا ہوجائیں تو قوم تباہی سے بچ جاتی ہے مثلاً تعلیم اگر کسی قوم
Page 488
میں آ جائے، سچ کی عادت اگر کسی قوم میں راسخ ہو جائے، محنت کی عادت اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائے، قربانی اور ایثار کا مادہ اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ قوم ترقی کر جاتی ہے.یہ بھی جزا و سزا ہی ہے.چنانچہ جن قوموں میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ان باتوں کاکوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور پیدا ہوتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتی اور ترقی کر جاتی ہیں.یورپ کی قومیں چونکہ عیسائیت کی قائل ہیں.اس لئے وہ جزا و سزا کی منہ سے قائل ہیں مگر عملاً دہریہ ہیں آئندہ زندگی کی امید ان میں سوائے جُہّال کے یا سوائے پادریوں کے ایک خاص طبقہ کے اور کسی میں نہیں پائی جاتی.لیکن انہوں نے تاریخ کے گہرے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ ضرور نکال لیا ہے کہ عام طور پر لوگوں میں جو یہ خیال پایا جاتا ہے کہ بعض کام بے نتیجہ رہ جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کوئی کام بے نتیجہ نہیں رہتا انفرادی کام بھی اور قومی کام بھی.ہر کام کے نتائج آخر ضرور نکلتے ہیں.اچھے کام کے اچھے نتائج نکلتے ہیں اور برے کام کے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں.پس خدا تعالیٰ کی رضا مندی یا نا رضامند ی کی خاطر نہیں بلکہ جو قانون قدرت انہیں دنیا میں رائج نظر آتا ہے اسے دیکھتے ہوئے وہ اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ ایسا کوئی فعل نہیں جو بے جزا یا بے سزاکے رہے.اس وجہ سے وہ قومی اخلاق پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سچ اس لئے نہیں بولتے کہ خدا تعالیٰ خوش ہوگا وہ سچ اِس لئے نہیں بولتے کہ سچ بولنے سے جنت ملتی ہے بلکہ وہ سچ اس لئے بولتے ہیں کہ سچ کے بغیر اعتبار پیدا نہیں ہو تا اور اعتبار کے بغیر تعاون پیدا نہیں ہوتا.یا اگر ہم سچ نہیں بو لیں گے تو غیر قوموں میں ہمارا اعتبار نہیں رہے گا اور ہماری تجارت ترقی نہیںکرے گی.ہندوستان کی غیر ملکوں سے کروڑوں روپیہ کی تجارت تھی جو جھوٹ بولنے کی وجہ سے سب کی سب تباہ ہو گئی.اس کے مقابلہ میں یورپ کا آدمی بھی انفرادی طور پر جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا ہے مگر وہ ایسا جھوٹ نہیں بولتا جو قومی نقصان کا موجب ہو.یہاں کسی دوکان دار سے جا کر کہہ دو کہ ہمارے گھر فلاں چیز بھجوا دینا تو وہ کبھی ویسی نہیںہو گی جیسی دوکان پر جا کر دیکھی گئی تھی.لیکن یورپ اور امریکہ میں آرڈر بھجواؤ تو چھ مہینہ یا سال کے بعد عین آرڈر کے مطابق چیز آجائے گی.تم کبھی غیر ملکوں میں اس قسم کا تمسخر نہیں دیکھو گے جیسے ہمارے ملک میں ہو تا ہے کہ اخبارات میں اشتہار شائع کئے جاتے ہیں کہ اگر فلاں چیز کا ہمیں آرڈر دیا جائے تو ہم ایک گھڑی مفت دیں گے حالانکہ وہ چھ آنے کی گھڑی ہو تی ہے مگر نام انعام رکھا جاتا ہے جو صریح دھوکا بازی ہو تی ہے.یا قلم وہی ہو گی جو اڑھائی آنے کی جرمنی سے آتی ہے اور اشتہار یہ دیا جا تا ہے کہ ایک فونٹن پن مفت دیا جائے گا.یہ دھوکا اور فریب یورپ میں نہیں.اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ قومی کیریکٹر اچھا نہ ہو تو تجارتیں نہیں چل سکتیں.انہوں نے چونکہ غیر ملکوں میں اپنا مال بیچنا ہو تا ہے اس لئے وہ ایسی طرز پر کام کرتے ہیںکہ ان کے وقار کا سکہ بیٹھا رہتا ہے خصوصاً انگلستا ن اور
Page 489
امریکہ میں یہ بات نہایت نمایاں طور پر پائی جاتی ہے.جرمنی میں ایک حصہ ایسا تھا جو فریب کاری کرتا تھا مگر عام طور پر جرمنوںمیں بھی یہ بات نہیں تھی پھر انگلستان اور امریکہ کے بعد سوئٹزر لینڈ نےبھی تجارت میں خاص طور پر ترقی کرلی ہے کوئی مال منگواؤ بالکل ویسا ہی آئے گا جیسا آرڈر دیا گیا تھا.فرانس سے منگواؤ تو وہ نوّے فیصدی ٹھیک ہو گا لیکن ہندوستان کے کسی دوکان دار کو آرڈر دو وہ نوّے فیصدی خراب مال بھجوائے گا.پس جزا و مکافاۃ کہ یہ معنے نہیں کہ خدا کی طرف سے جو جزا و مکافاۃ ملتی ہےبلکہ جو شخص بھی جزا و مکافاۃ پر یقین نہیں رکھےگا خواہ قومی اخلاق کے نتائج پر اس کا یقین نہ ہو گا اور خواہ خدا تعالیٰ پر ا س کا یقین نہیں ہو گا اس کا کیریکٹر ضرور خراب ہو جائے گا.بعض احمق فلاسفر کہہ دیا کرتے ہیں کہ کسی انعام کی خاطر کام کرنا یا کسی سزا کے خوف سے کام کرنا اچھے اخلاق میں شمار نہیں ہو سکتا.اصل میں یہ فلاسفروں کا نہیں بلکہ پادریوں کا ایک احمقانہ نظریہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں جس قدر فلسفہ یورپ میں پڑھایا جاتا تھا وہ پادریوں کے سکولوں میں ہی پڑھایا جاتا تھا.پادری ہی پروفیسر ہوتے تھے اور تمام کالج انہی پادریوں کے ماتحت ہو تے تھے اس لئے یوروپین فلسفہ میں کئی ایسی چیزیں داخل ہو گئی ہیں جو مذہب سے رنگین ہیںجیسے ہمارے ابتدائی زمانہ کے علوم بھی بہت حد تک مذہب سے متاثر نظر آتے ہیں لغت کو لے لو، شعر کو لے لو، تفسیر کو لے لو.سب میں مخصوص مذہبی عقائد کی جھلک پائی جائے گی.اس لئے ہمارے علوم میں بھی کئی غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں.فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے مذہب نے فلسفہ میں دخل نہیں دیا لیکن یورپ کے مذہب نے فلسفہ میں بھی دخل دیا ہے.ہمارے مذہب نے طب میں دخل نہیں دیا لیکن یورپ کے مذہب نے طب میں بھی دخل دیا ہے.ہاں ہمارے مذہب نے لغت میں دخل دیا ہے اور اس کا اثر لغت میں صاف طور پر نظر آتا ہے.بعض دفعہ کسی مقام پر قرآن کریم کی لغت حل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور ہم لغت دیکھتےہیں تو وہ ان معنوں کی تائید میں جن کی ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں زیر بحث آیت کو ہی مثال میں پیش کر دیں گے اور اس سے تحقیق تشنہ رہ جائے گی.یہ ایک کمزوری ہے جوعربی لغت میں پائی جاتی ہے.اگر خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو وہ لغت سے اس قسم کی باتوں کو ضرور نکال دے جو مذہبی عقیدہ کی وجہ سے اس میں داخل کر دی گئی ہیں.ان باتوں کی موجودگی قرآن کریم کی خدمت نہیں بلکہ اس پر ظلم ہے.اس لئے کہ جب کوئی شخص جھوٹا راستہ اپنے لئے نکالتا ہے تو وہ علم کے دروازہ کو بند کر دیتا ہے.قرآن کریم تو خدا کی کتاب ہے انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ صحیح ہے اورانہیں غور کرنا چاہیے تھا کہ اگر ان کے علم کے مطابق لغت میں اس کے کسی لفظ کے معنے نہیں ملتے تو وہ اور کوشش کریں خدا تعالیٰ ان پر ضرور کوئی راستہ تحقیق کاکھول دے گا یہ کیا کہ قرآن کریم کے کسی لفظ کے معنوںکی تلاش
Page 490
میںخود اسی آیت کو پیش کر دیا جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے اور ا س کے معنے لغت کے مطابق نہیں بلکہ تفسیر کے مطابق کر دیئےحالانکہ لغت نے تو ہمیں یہ نتیجہ نکالنے میں مد د دینی تھی کہ جو معنے ہم نے سمجھے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں.اگر یہ لوگ جلد بازی کی بجائے غور کرتے تو لغت میں بھی زیادتی ہوتی اور قرآن کریم کے معارف میں بھی زیادتی ہوتی.مگر چونکہ انہوں نے جھوٹا راستہ اختیار کیا اس لئے جو کسی سابق مفسّر نے اس آیت کی تفسیر میں کسی خاص لفظ کے معنے کئے تھے وہی انہوں نے اس لفظ کے لغت میں معنے لکھ دیئے اور لغت کو قرآن کریم کی خدمت سے محروم کر دیا اور یہ غلطی ایک دو مقام پر نہیں کی گئی بلکہ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے بارہ میں یہ غلطی کی گئی ہے.سب سے بڑی لغت کی کتاب لسان العرب ہے.اس کو ہی دیکھا جائے تو اس میں بھی بعض مقامات پر یہ نقص نظر آئے گا.ایک لفظ جس کے معنے وہ لکھ رہے ہیں اگر قرآن کریم میں اس کا استعمال لغت کے معروف معنوں کے خلاف نظر آیا ہے تو انہوں نے تفسیری معنے اس لفظ کے لکھ کر ا س کی سند میں قرآن کریم کی زیر بحث آیت لکھ دی.حالانکہ چاہیے تھا کہ تفسیری معنوں کو یا تو ردّ کرتے کہ یہ لغت کے خلاف ہیں یا پھر عربوں کے محاورہ سے مثالیں دے کر ثابت کرتے کہ یہ تفسیری معنے درست ہیں اور عرب ان معنوں میں اس لفظ یا جملہ کو بولتے ہیں.آیت کو ہی دلیل کے طور پر پیش کر دینے سے اعتراض دور نہیں ہو تا.بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے.اگر وہ زیادہ تحقیق کرتے تو یقیناً اس کے کئی حل نکل آتے مگر انہو ں نے جلد بازی سے کام لیا اور اس طرح یہ نقص رہ گیا.چونکہ پادریوں کا بھی یوروپین فلسفہ کی تعلیم میں دخل تھا اس لئے انہوں نے اسلام پر اعتراض کرنے کے لئے فلسفہ میں ایسی کئی باتیں داخل کر دیں جو در حقیقت کسی فلسفہ کا نتیجہ نہیں بلکہ قرآن پر اعتراض کرنے کے لئے انہوں نے ان مسائل کو فلسفہ میں شامل کر دیا.چونکہ قرآن کریم بار بار اس مسئلہ کو پیش کرتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت اور دوزخ ہو گی.اس لئے انہوں نے فلسفہ کے نام سے یہ بحث اٹھا دی کہ جو کام انسان عذاب کے ڈر کے مارے کرتا ہے یا انعام کی خواہش سے کرتا ہے وہ کوئی نیکی نہیں بلکہ نہایت ادنیٰ درجہ کا خُلق ہے.مگر یہ بالکل جھوٹ ہے اگر یہ ادنیٰ اخلاق ہیں تو دنیا میں اخلاق ہیں ہی نہیں.کون سا کام ہے جو انسان ڈر کے مارے نہیں کرتا یا کون سا کام ہے جو انسان کسی فائدہ کی امید میںنہیں کرتا.یہی پادری ؟ اعتراض کرنے والا ہے اگر ا س کے سامنے پاؤ بھر مرچیں رکھ دی جائیں اور اسے کہا جائے کہ یہ مرچیں کھاؤ تو کیا وہ کھا لے گا.وہ کہے گا میں مرچیں نہیں کھا سکتا کیونکہ مجھے پیچش ہوجائے گی اب کیا ڈر کے مارے اس نے مرچوں کو چھوڑا یا نہیں.مگرکیا یہ بدی ہو جائے گی ؟ اگر ڈر کے مارے کسی کام کو چھوڑنا برا ہے تو یہ قانون اور تعزیرات وغیرہ کیوں ہیں اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر چور چوری کرے گا تو اسے
Page 491
اتنی سزا دی جائے گی.اگر مسیحی فلسفہ کا یہ نکتہ درست ہے تو یہ ساری گورنمنٹیں قانون اخلاق کو بگاڑنے والی ہیں.قانون اخلاق اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ ہم کسی کو چوری کی سزا نہیں دیں گے اگر کسی نے چوری چھوڑنی ہے تو خود بخود چھوڑ دے یا ہم کسی کو قتل کی سزا نہیں دیں گے اگر کسی نےقتل چھوڑنا ہے تواپنی مرضی سے چھوڑ دے.مگر کیا دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسی بات مان سکتی ہے ؟ محض قرآن اور اسلام پر اعتراض کرنے کے لئے پادریوں نے اپنامنہ کالا کیا ہے اور ایک ایسا فلسفہ بنا کر پیش کر دیا ہے جو نہ یورپ میں رائج ہے نہ امریکہ میں رائج ہے نہ فرانس میں اور نہ جرمنی میں رائج ہے اور نہ عملاً دنیا میں ایسا ممکن ہے.وہی پروفیسر جو کالج میں یہ پڑھاتا ہے کہ سزا کے خوف سے کام کرنا سخت برا ہو تا ہے یا جزا کی امید سے کام کرنا بد اخلاقی ہے وہ خود اس قانون پر عمل نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ تنخواہ لے کر پڑھا رہاہوتا ہےاور اگر اس کا نوکر غلطی کرتا ہے تو وہ اسے آٹھ آنے جرمانہ کر دیتا ہے.اب کیا آٹھ آنے جرمانہ وہ اپنے نوکر کے اخلاق کو بگاڑنے اور اس کے معیارِ اخلاق کو گرانے کے لئے کرتا ہے.اگر سزا کا خوف دلانا انسا ن کے اخلا ق کو بگاڑتا ہے تو وہ اپنے نوکر کو سزا کا خوف کیوں دلاتا ہے وہ اسے جرمانہ کیوں کرتا ہے ؟ محض اس لئے کہ وہ خود اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا میں انسان مختلف معیارِ اخلاق کے ہیں.کسی پر سزا زیادہ اثر کرتی ہے کسی پر انعام زیادہ اثر کرتا ہےاور کوئی ایسا ہو تا ہے جو عشق کے مقام پر ہو تا ہے وہ سزا اور انعام سب کچھ بھول جاتا ہے.بہرحال ابتدائی درجہ خوف کا ہے دوسرا درجہ انعام کی امید کا ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی عادت ہو جاتی ہےاور وہ نیکی کے فلسفہ پر غور کر کے اس کے ذاتی جوہر سے واقف ہوجاتا ہے اور پھر وہ نیکی کو محض اس کی محبت اور رغبت کی وجہ سے کرتا ہے کسی انعام کی خواہش یا کسی سزا کے ڈر سے نہیں کرتا اور سب سے مقدّم درجہ یہ ہے کہ کسی اعلیٰ مثال کی نقل میں تکمیل نفس کی خاطر نیکی کی جائے.اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کردو تو بنی نوع انسان کا بیشتر حصہ گناہوں اور بدیوں میں مبتلا ہو جائے گا.پس یہ فلسفہ محض اسلام کی دشمنی کے نتیجہ میں پادریوں نے پیش کر کے اپنا ناک کاٹا ہے.مسلمان جب تک ان کے فریبوں سے واقف نہیں تھا وہ ان باتوں سے متاثر ہو جاتا تھا.مگر جب یہ اعتراض ان لوگوں تک پہنچے جو قرآن کریم کو سمجھتے تھے تو ان کا سارا فریب کھل گیا.غرض جزا و سزا سے مراد یہاں اخروی جزا و سزا نہیں.میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں اخروی جزا و سزا لازمی نہیں.یہ مطلب نہیں کہ اس جزا و سزا کا ردّ ہے.بہر حال جزا و سزا کا احساس یعنی اس بات کا کہ اچھے اخلاق سے قوم ترقی کرتی ہے اور برے اخلاق سے قوم بگڑ جاتی ہےیا اچھے اطوار سے قوم ترقی کرتی ہے اور برے اطوار سے قوم بگڑ جاتی ہے.یا جو قومیںبرے کام کرتی ہیں آخر کسی نہ کسی وقت اس کی سزا کو بھگتتی ہیں.یا خدا تعالیٰ کو ماننے والے کا یہ یقین
Page 492
کہ خدا تعالیٰ میرے برے اعمال کی ضرور سزا دے گا خواہ دنیا میں دے یا اگلے جہان میں.یا اچھے اعمال کا مجھے ضرور انعام دے گا خواہ دنیا میں دے یا اگلے جہان میں.یہ خیال کسی فرد یا قوم میں پیدا ہو جانا اسے بری باتوں سے ضرور روکتا ہے.یہ اتنی ثابت شدہ اور صاف بات ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کوئی جان بوجھ کر اندھا ہو جائے.پس اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ میں جب دِیْن کے معنے جزا و مکافاۃ کے لئے جائیں تواس آیت کے یوں معنے ہو ں گے کہ مجھے بتا تو سہی وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ دنیا میں جزا و سزا نہیں.وہ بےشک میرا انکار کر دے وہ بے شک خدا کو نہ مانے مگر یہ لازماً ہر انسان کو ماننا پڑے گا کہ کچھ اعمال قوموں یا انسانوں کو تنزّل کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ اعمال قوموں یا انسانوں کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں.یہ ایسا ثابت شدہ اصل ہے کہ جو شخص اس کا انکار کرے گا وہ ضرور تنزّل کی طرف جائے گا اور ضرور برائیوں میں مبتلا ہوجائے گا.(۲)دوسرے معنے اس کے یہ ہیں کہ تو مجھے بتا تو سہی وہ کون ہے جو اطاعت کا منکر ہے.اطاعت سے مراد نظام اور ضبط کے ہیں غلامی نہیں.غلامی کا قرآن اور اسلام دشمن ہے بلکہ سب سے پہلا مذہب جس نے دنیا سے غلامی کو اڑایا وہ اسلام ہے مگر یہ ایک الگ مضمون ہے.لوگ غلطی سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں غلامی جائز ہے میں سارا قرآن سامنے رکھ دیتا ہوں کوئی شخص مجھے ایک ہی ایسی آیت نکال دے جس میں غلامی کو جائز قرار دیا گیا ہو.مجھے تو اب تک کوئی ایسی آیت نہیں ملی حالانکہ معترض سے سینکڑوں گُنے زیادہ میں نے قرآن پڑھا ہو گا.پس جس چیز کو غلامی کہتے ہیں وہ قرآن میں نہیں نہ کسی حدیث میں ہے.میں مانتا ہوں کہ مسلمانوںمیں غلطی سے غلا می کا رواج رہا ہے مگر مسلمانوں کی غلطی سے قرآن اور اسلام پر اعتراض عائد نہیں ہو سکتا.جب ہندو یہاں تھے اس وقت بھی مسلمان سینما دیکھا کرتے تھے اور اب ہندو چلے گئے ہیں تب بھی مسلمان سینما دیکھتے ہیں.ناچ گانا پہلے بھی ہوا کرتا تھا اور ناچ گانا اب بھی ہوتا ہے.ریڈیو پر خبریں سننے لگو تو بدبختی آجاتی ہے.اسے ذرا کھولیں تو فوراً ہا ہا کی آوازیں آنی شروع ہوجاتی ہیں.اسی طرح مسلمانوں میں بے پردگی ہے.مسلمان شرابیں پیتے ہیں اور اتنی کثرت سے پیتے ہیں کہ ابھی سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اگر رمضان میں ہم شراب روکیں گے تو گورنمنٹ کو دس لاکھ روپیہ کا نقصان ہوگا.اوّل تو میری سمجھ میں ہی یہ بات نہیں آئی کہ اگر دس لاکھ کا گورنمنٹ کو نقصان ہو گیا تو کیا ہوا.مگر اس سے بھی زیادہ جس چیز نے مجھے پریشان کر دیا وہ یہ ہے کہ دس لاکھ ماہوار نقصان کے معنے یہ ہیں کہ سندھ میں ماہوار پچاس لاکھ روپیہ کی شراب پی جاتی ہے.سارے پاکستان کی آبادی سندھ سے بارہ گنے زیادہ ہے اگرصرف سندھ میں پچاس لاکھ روپیہ ماہوار شراب پر صرف کیا جاتا ہے تو اس کے معنے یہ ہیں کہ چھ کروڑ روپیہ سالانہ کی شراب
Page 493
سندھ میں پی جاتی ہے اور اگر اسی پر باقی پاکستان کا بھی قیاس کیا جائے تو چونکہ پاکستان کی آبادی سندھ سے بارہ گنے زیادہ ہے اس لئے معلوم ہوا کہ بہتّر کروڑ روپیہ کی شراب صرف پاکستان کے مسلمان پیتے ہیں.میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی لیکن اگر ایسا ہی ہے تو کیا اس کا ذمہ دار اسلام ہے ؟ اسلام تو کہتا ہے کہ شراب نہ پیو.پس یہاں وہ اطاعت مراد نہیں جسے غلامی کہتے ہیں.قرآن جس کو اطاعت کہتا ہے وہ نظام اور ضبط ِ نفس کا نام ہے یعنی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انفرادی آزادی کو قومی مفاد کے مقابلہ میں پیش کر سکے.یہ ہے ضبطِ نفس اور یہ ہے نظام.تمام قانون جو دنیا میں بنتے ہیںتمام گورنمنٹیںجو ذرائع نقل وحرکت، ریلوے، پاسپورٹ اور تجارتوں کے متعلق قانون بناتی ہیں تمام ملک کی آبادی اس کے ماتحت ہو تی ہے حکومتیں کہتی ہیں کہ فرد بے شک آزاد ہےمگر اسے ایسی آزادی حاصل نہیں کہ وہ قوم کو نقصان پہنچائے ہم فرد کو زیادہ سے زیادہ آزادی دیں گے مگر جہاں اس کا فائدہ قوم کے فائدہ سے ٹکرا جائے گا ہم اسے آزادی نہیں دیں گے.یہ قانون ہے جو ایک لمبے تجربہ اور کشمکش اور جھگڑوں اور لڑائیوں کے بعد نکھر نکھرا کر اس صورت میں نکل آیا ہے اور تمام متمدّن دنیا کم سے کم اس وقت اس کو صحیح تسلیم کرتی ہے.اسی کی طرف قرآن کریم نے قریباً چودہ سو سال پہلے اشارہ فرمایا اور کہا اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ.مجھے اس شخص کی خبر دےجو نظام و ضبط ِ نفس کا قائل نہیں یعنی پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ وہ اپنے اور اپنی قوم کے لئے ہرگز کسی عزت کا موجب نہیں بن رہا.لازماً اس سے بد افعالیاں اور بد اعمالیاں ظاہر ہوں گی.مذکورہ بالا قانون کو توڑنے کے بعد کوئی شخص نیکی پر قائم ہی نہیں رہ سکتا.یہ کیا لطیف مضمون ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے.یورپ کا کوئی ایک فلسفی بھی ایسا پیش نہیںکیا جا سکتا جس کی دس جلدوں کی کتاب میں بھی قومی کیریکٹر کے متعلق وہ مضمون بیان ہوا ہو جو اس چھوٹے سے فقرہ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ.یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں اتنا مضمون ہے کہ اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں.فرماتا ہے ضبطِ نفس یا نظام کا انکار کر کے اگر کوئی کہے کہ میں نیک رہ سکتا ہوں تو یہ بالکل غلط بات ہے وہ ضرور خرابی اور فساد کا موجب ہو گا.مثلاً گورنمنٹیں قانون بناتی ہیں کہ بائیں طرف چلویا یہ کہ دائیں طرف چلواب اگر کوئی کہے کہ میں کیوں اس پر عمل کروں.جب سڑک پر چلنے کی عام اجازت ہے تو میں تو سڑک کے جس طرف چا ہوں گا چلوں گا دائیں یا بائیں نہیں چلوں گا.اس شخص کا انجام ظاہر ہے کہ یہ کسی گاڑی سے ٹکرا کر زخمی ہو گا یا سامنے سے آنے والوں سے قدم قدم پر ٹکرائے گا اور سب مسافروں کے لئے تکلیف کا مو جب ثابت ہو گا.حقیقت یہ ہے کہ نظام کی پابندی کے بغیر دنیا میں امن قائم ہی نہیں رہ سکتا.پس کسی کا یہ کہنا کہ میں فلاں قانون کیوں مانوں ایک فساد کا راستہ ہے مگر نظام کی پابندی کے
Page 494
یہ معنے بھی نہیں کہ چند افراد اپنے ہاتھ میں حکومت کے اختیارات لے لیں اور جس طرح چاہیں لوگوں پر دباؤ ڈالیں.ابھی سِوَل میں مَیں نے پڑھا ہے کہ راولپنڈی یا لائل پور میں ایک شخص نے روزہ نہیں رکھا تھا لوگوں نے اس کا منہ کالا کر کے تمام بازار میں پھرایا.اب اگر وہ شخص احتجاج کرے کہ پبلک کو اس بات کا کیا حق ہے کہ وہ نظام کو اپنے ہاتھ میں لے تو یہ بالکل ٹھیک ہو گا پبلک کو ہر گز اس قسم کا کوئی حق نہیں.خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا واقعہ ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے پاس ایسی حالت میں بیٹھا دیکھوں جس کے معنے یہ ہوں کے وہ شخص زنا کر رہا ہے تو یا رسول اللہ کیا میں اسے مار ڈالوں ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گز نہیں.اس نے کہا یا رسول اللہ ! اسلام تو ا س کے لئے قتل ہی کی سزا تجویز کرتا ہے (اس وقت تک ابھی رجم پر ہی عمل ہوتاتھا ) آپ نے فرمایا ٹھیک ہے.اس صحابی نے کہا جب اسلام بھی اس کے لئے یہی سزا تجویز کرتا ہے تو اگر میں خود ہی اسے مارڈالوں تو اس میں کیا حرج ہے ؟ آپ نے فرمایا اگر تم اسے مارو گے تو تم قاتل سمجھے جاؤگے تم اسے قاضی کے پاس لے جاؤ اور اس کے سامنے مقدمہ پیش کرو.اپنےہاتھ میں قانون لینے کا تمہیں اختیار نہیں(بخاری کتاب الطلاق باب اللعان و من طلق بعد اللعان).غرض جو قانون گورنمنٹ نے بنایا ہے اس میں گورنمٹ کے قاضی کا فیصلہ لینا ضروری ہو گا.ورنہ اس سے امن نہیں بلکہ فساد اور بدامنی پیدا ہو گی یا جو قانون سوسائٹی نے بنایا ہے اس میں سوسائٹی کا قاضی فیصلہ کرے گا یا پنچ وغیرہ کریں گے ہر ایک کو حق نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور مجرم کو سزاد ینی شروع کر دے.ہزاروںہزار دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے پر الزام ثابت ہے مگر قاضی کہتا ہے کہ الزام ثابت نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس اس طرح جرم ثابت ہو تب دوسرا شخص مجرم ثابت ہو گا اور اگر اس طرح جرم ثابت نہیں ہو گا تو اسے بَری قرار دیا جائے گا کیونکہ قانون نے غیرمجرموں کو بچانے کے لئے ثبوت کے معیارزیادہ سخت تجویز کئے ہوئے ہیں.اگر نرم ہوتے تو کئی غیر مجرموں کو بھی لوگ پھنسا دیتے.پس قانون نے نا کردہ گناہ لوگوں کو سزا سے محفوظ رکھنے کے لئے ثبوت کے معیار پبلک کے نقطہ نگاہ کے مقابلہ میں زیادہ سخت رکھے ہوئے ہوتے ہیں.اگر پبلک کو یہ اختیار ہو تا کہ وہ جس کو چاہے سزادے دے تو وہ اپنی ناتجربہ کاری کے ماتحت کئی غیر مجرموں کو بھی سزا دے دیتی.بہر حال قانون کا منشا صرف مجرم کو سزا دینا نہیں ہو تا بلکہ اس کا یہ بھی منشا ہو تا ہے کہ کوئی غیر مجرم اس سزا کا مستحق نہ بن جائے.پبلک تو سمجھتی ہے کہ ہمیں جس کے متعلق کوئی شبہ ہوگیا ہے اسے ہم سزا دے دیں لیکن قانون کا دماغ منصفانہ ہوتا ہے.وہ سزا تو دیتا ہے مگر ایسے طور پر جرم ثابت کرتا ہے کہ غیرمجرم مجرم ثابت نہ ہو اور سزا صرف اسی کو ملے جس نے جرم کیا ہے.تو اللہ تعالیٰ
Page 495
فرماتا ہے ضبط ِ نفس اور نظام کا جو شخص منکر ہوگا وہ گناہ میں ضرور مبتلا ہو گا.ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں سے یہ غلطی ہو گئی ہے کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں ؟ میں ہمیشہ انہیں کہا کرتا ہوں کہ تم محکمہ کولکھواور پھر جو کچھ وہ فیصلہ کرےاس کے مطابق عمل کرو تمہارا حق نہیں کہ تم خودبخود اس بارہ میں کوئی فیصلہ کر لو کیونکہ ممکن ہے تمہاری اس سے دشمنی ہو اور تمہاری رائے آزادانہ نہ ہو پس قانون شکنی اور چیز ہے اور قانون شکنی کا ثبوت اور چیز ہے.اور وہ بھی نہایت ضروری ہے.اس کےبغیر کوئی نظام قائم نہیں رہ سکتا.پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص نظام کی پابندی کرے گا وہ تبھی ایسا کرے گا جب اسے یقین ہو گا کہ قومی ترقی فردی ترقی کی ضامن ہوا کرتی ہے.اس وقت دنیا میں دو نظریے پائے جاتے ہیں ایک یہ کہ چونکہ قوم فرد سے بنی ہے اس لئے فردی ترقی ہی اصل مقصود ہےاس عقیدہ کے قائل لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام زیادہ ضروری نہیں اگر افراد کی ترقی میں نظام قومی روک بن جائے تو ان کا حق ہے کہ وہ اس نظام کو توڑ دیں.لیکن بعض اور لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ قومی ترقی فردی ترقی کی ضامن ہو تی ہے.ا ن کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ فردی آزادی کو قائم رکھنا بےشک قوم کے ذمہ ہے لیکن فرد کو اپنے طور پر یہ اختیار نہیںکہ وہ قومی قانون کو اپنے مفاد کے خلاف دیکھ کر توڑ دے اگر وہ سمجھتا ہے کہ قومی قانون فرد کی ترقی میں روک بن گیا ہے تو وہ مقررہ ذرائع سے اس قانو ن کو بدلوا سکتا ہے مگر اس کا یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ ہی آپ اس کو توڑنا شروع کر دے.اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ کایہی مفہوم ہے کہ جو بھی قومی ترقی کے اوپر فردی ضرورت کو غالب کرے گا وہ ضرور خود غرضی کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گااور ذاتی جلبِ منفعت کے لئے مختلف قسم کے ایسے کام شروع کر دے گا جن سے قوم میں غلطیاں پیدا ہو جائیں گی اور کئی قسم کے گناہوں کا دروازہ کھل جائے گا.(۳) اس آیت کے تیسرے معنےغلبہ کےمنکر کے ہیں.غلبہ کے منکر سے بھی یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ محض غلبہ کا منکر.کیونکہ محض غلبہ تو دنیامیںکسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہی ہے.ملک میں انتظام نہیں ہو تا تو چور اور ڈاکو غالب ہوتے ہیں.انتظام ہوتا ہے تو حکومت غالب ہو تی ہے.یہ تو دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی غالب اور کوئی مغلوب نہ ہو.پس اس سے مراد محض غلبہ نہیں ہو تا بلکہ حق اور انصاف کا غلبہ مراد ہے.پس اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ کےایک معنے یہ ہوئے کہ مجھے بتا تو سہی کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ یقین نہیں رکھتے کہ آخر نیک اعمال ہی کی فتح ہوتی ہے.جو شخص بھی یہ خیال رکھے گا کہ نیک اعمال کی فتح ضروری نہیں وہ بدی میں ضرور مبتلا ہو گا جیسے ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں.ایہہ جگ مٹھّا تے اگلا کنِّ ڈٹھّا
Page 496
جس شخص کا یہ عقیدہ ہو گا کہ نیکی آخر کار غالب نہیں آتی وہ لازماً بدی میں مبتلا ہو جائے گا کیونکہ اس کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہو گی.کوئی بدی کے مقام سے کھینچنے والا جذبہ اس کے اندر کام نہیں کر رہا ہو گا.وہ سمجھے گا کہ بہر حال میں نے اپنا یا اپنی قوم کا کام کرنا ہے اگر اس کے لئے مجھے برا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا تو میں برا ذریعہ اختیار کر لوں گا اور اگر اچھا ذریعہ اختیار کرنا پڑا تو اچھا ذریعہ اختیار کر لوں گا.نیک ذریعہ اختیار کرنے میں چونکہ قربانی کرنی پڑتی ہے اس لئے یہ لازمی بات ہے کہ ایسا شخص گناہ اور بدی کے راستوں کو زیادہ اختیار کرے گا.لیکن جو شخص یہ سمجھے گا کہ آخر نیکی ہی کی فتح ہو تی ہے یہ لازمی بات ہے کہ وہ اپنے نفس کو روکتا رہے گا اور سمجھے گا کہ اگر مجھے عارضی نقصان پہنچتا ہے تو کیا حرج ہے میں عارضی فائدہ کے لئے اپنا دائمی نقصان کیوں کر لوں.اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خیال کہ آخرمیں نیکی کی فتح ہو تی ہے کبھی بھی قیامت پر یقین کے بغیر پیدا نہیں ہوتا.جو شخص قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ نیکی کے آخری غلبہ پر بھی کبھی یقین نہیں رکھ سکتا.مثلاً یورپ کے فلاسفر سب اس بات پر متفق ہیں اور زور دیتے ہیں کہ نیکی کو نیکی کی خاطر کرنا چاہیے یا دوسرے لفظوں میں اس کے یہ معنے بنتے ہیں کہ خالص نیکی ہی آخرغالب آیا کرتی ہے.مگر کوئی ایک یوروپین ملک بھی تو ایسا نہیں جس کی سیاست اس پر مبنی ہو.ان کی تمام سیاست اس بات پر چکر کھاتی ہے کہ ہماری قوم کو غلبہ ملنا چاہیے اس کے لئے وہ ناجائز ذرائع بھی اختیار کریں گے اور دھوکا بازیاں اور فریب بھی کرتے رہیں گے انگریزی کی ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ END JUSTIFIES THE MEANS یعنی اگر ہمارا مقصد نیک ہو تو اس کے حصول کے لئے جو ذرائع بھی اختیار کئے جائیں خواہ کتنے برے ہوں وہ جائز اور درست ہی سمجھے جائیں گے.یہ نظریہ ان میں کیوں پیدا ہوا ہے اسی لئے کہ ان کو اُخروی زندگی پر ایمان نہیں وہ کہتے تو یہ ہیں کہ اصل چیز نیکی ہے اور نیکی کو نیکی کی خاطر کرنا چاہیے مگر جب وہ دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کرنے والا بعض دفعہ نقصان بھی اٹھا تا ہے اس لئے وہ یہ مسئلہ ایجاد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ نیکی کو سنبھالنے کے لئے اگر کچھ ستو ن بدی کے بھی کھڑے کرنے پڑیں تو حرج نہیں.کیونکہ اصل مقصد تو نیکی کو قائم کرنا ہے.لیکن جو شخص اُخروی زندگی پر ایمان لاتا ہےوہ اعمال کا انجام کلی طور پر اسی دنیا میں دیکھنے کا منتظر نہیں ہو تا وہ سمجھتا ہے کہ اگر نیکی پر کاربند رہتے ہوئے مجھے یا میری قوم کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچنے دو میرے اس دنیا کے نقصان کو اگلے جہان میں پورا کر دیا جائے گا.ایسا شخص نیکی کے قیام کے لئے برے ذرائع کو استعمال کرنے کی نہ جرأت کرتا ہے اور نہ اس کی ضرورت سمجھتا ہے.کیونکہ وہ اس دنیاکو اگلی دنیا کی ایک کڑی سمجھتا ہے اور اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ نیکی بہرحال
Page 497
غالب آئے گی خواہ اگلے جہان میں ہی کیوں نہ غالب آئے.یہی وجہ ہے کہ نیکی کے اعلیٰ معیار پر کبھی خدا پرست کے سوا اور کوئی شخص قائم نہیں ہوا.یوں اخلاقِ فاضلہ پر یورپ کے فلاسفر بڑا زور دیں گے اور بیسیوں باتیں اپنی کتابوں میں لکھ دیں گے.چنانچہ ہکسلے، سپنسر، ہیگل اور کینٹ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو ان کے دیکھنے سے یوں معلوم ہو گا کہ شاید ان میں مذہبی لوگوں سے بھی زیادہ نیکیاں پائی جاتی ہیں.مگر جب ان کے ذاتی کیریکٹر کو دیکھا جائے تو وہ نبیوں کے غلاموں کے غلاموں کے برابر بھی نہیں ہوتے.اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف باتیں بھگارتے ہیں ورنہ ان کے دل میں صرف اتنی بات ہو تی ہے کہ ہمیں اپنا فائدہ چاہیے خواہ وہ کسی طرح سے حاصل ہو.چنانچہ جب انہیں نیکی کے معیار غلط نظر آتے ہیں اور کسی کام میں انہیں اپنا نقصان دکھائی دیتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیںاور سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے فائدہ کی کوئی صورت پیدا کرنی چا ہئے.ادھر ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی خطرہ کی صورت ہو یا کیسی ہی مشکلات ہوں ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں آتا.گلیلیو نے جب یہ تحقیق کی کہ سورج زمین کے گرد چکر نہیں کھاتا بلکہ زمین سورج کے گرد چکر کھاتی ہے تو پادریوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ بائبل میں تو یہ لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر بنایا ہے اور جب انسان خدا کی شکل پر ہے اور انسان اس زمین پر رہتا ہے تو لازماً یہ زمین اعلیٰ ہوئی.مگر یہ اتنا بڑا کفر بکتا ہے کہ کہتا ہے وہ زمین جس پر خدا نے انسان کو بنایا وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے.چنانچہ انہوں نے گلیلیو کو مختلف قسم کی اذیتیں پہنچانی شروع کر دیں.کچھ مدّت تک تو وہ مقابلہ کرتا رہا مگر آخر اس نے اعلان کیا کہ میں اب سمجھ گیا ہوں.در اصل شیطان نے مجھے کافر اور بے دین بنانے کے لئے ورغلا دیا تھا اور مجھے یہ نظر آنے لگا کہ زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے لیکن یہ غلط تھا زمین سورج کے گرد چکر نہیں کاٹتی بلکہ سورج زمین کے گرد چکر کاٹتا ہے کیونکہ دین میں ایسا ہی لکھا ہے.اس لئے میں اپنے پہلے عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں.یہ کتنی چھوٹی سی بات تھی مگر کہاں گئی اس کی صداقت اور کہاں گیا اس کا دعویٰ.یہی یورپ کے آج کل کے فلسفیوں کا حال ہے.کتابوں میں کچھ لکھتے ہیں مگر جب ذاتی اغراض کا سوال آجائے یا قومی مفاد اور لڑائیوں کا سوال آجائے تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں.اس وقت سارا فلسفہ انہیں بھول جاتا ہے.ادھر وادیٔ غیر ذی زرع کا رہنے والا ایک شخص جو پڑھا لکھا نہیں تھا.جو دستخط کرنا بھی نہیں جانتا تھا.جس کا صرف اتنا دعویٰ نہیں تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہےبلکہ وہ اپنی قوم اور ملک کے رسم و رواج اوراس کے عقیدوں کےخلاف ساری دنیا میں اعلان کرتا تھا کہ اس دنیا کا ایک خدا ہے.جب اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی تو وہ نڈر ہو کر ان کے مقابلہ پر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ
Page 498
ایک لمبے مقابلہ کے بعد اس کی قوم نے یہ تدبیر کی کہ اس کے چچا کا اس پر بڑا اثر ہے اگر اس کے ذریعہ اسے سمجھایا جائے اور وہ بھی یہ دباؤ ڈالے کہ اگر تم نے اس طریق کو جاری رکھا تومیں بھی تمہیں چھوڑ دوں گا تو ممکن ہے یہ شخص سیدھا ہو جائے.اور یہ سوچ کر قوم کے بڑے بڑے لوگ اس کے چچا کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے ہم سے لڑائی کر رکھی ہے اور وہ بہت لمبی ہو گئی ہے.اب ہم تمہارے سامنے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ آ خر اس لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہےاگر دماغ خراب ہو گیا ہے تو اس کے علاج پر جو بھی خرچ آسکتا ہو وہ ہم خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں.یا کیا اس کو دو لت کی خواہش ہے اگر یہ ہے تو ہم اپنی تمام دولت جمع کر کے اس کا تیسرا حصہ اسے دےدیتے ہیں.ہم میں سے ہر بڑے سے بڑا مالدار اور ہر غریب سے غریب انسان بھی اپنی دولت کا تیسرا حصہ اس کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہے.یا پھر کیا اس کی یہ خواہش ہے کہ کسی اچھے خاندان میں اس کی شادی ہو جائے اگر اس کی یہ خواہش ہے تو ہم سارے رؤوسا کی لڑکیاں اس کے سامنے پیش کرنے کے لئے تیار ہیں وہ جس سے چاہے شادی کر لے.یا پھر کیا اسے حکومت کی خواہش ہے؟ اگر یہ بات ہے تو ہم حکومت اس کے حوالے کرنے کے لئے تیار ہیں.بتاؤ دنیا داری کے لحاظ سے اس سے زیادہ وسعت حوصلہ والی تجویز اور کیا ہو سکتی تھی اور کیا اس کے بعد ممکن تھا کہ چچا اپنے بھتیجے کی حمایت کر سکتا ؟ پھر قوم نے اتنی بڑی پیشکش کرنے کے بعد جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ ہم اس کے بدلہ میں یہ نہیں کہتے کہ تمہارا بھتیجا اپنا دعویٰ چھوڑ دے ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کی تردید نہ کرے اور باتوں کے متعلق وہ بے شک وعظ وغیرہ کرتا رہے.پھر انہوں نے کہا اے ہمارے رئیس! ہم تیرا بھی ادب کرتے ہیں اور در اصل تیری خاطر ہی ہم نے تیرے بھتیجے کو اب تک چھوڑا ہوا ہے.اگر تم سمجھتے ہو کہ ہماری یہ باتیں معقول ہیں تو تم اپنے بھتیجے کے سامنےان باتوں کو پیش کرو اور اسے منوانے کی کوشش کرو اور اگر تم اسے نہ منوا سکو اور خود بھی اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ تم اپنی قوم کو ہر طرح ذلیل کرنا چا ہتے ہو.ہم نے زیادہ سے زیادہ قربانی جو کی جا سکتی تھی کر دی ہے اب تمہارا فرض ہے کہ اپنے بھتیجے کو منواؤ اور وہ نہ مانے تو تم اس کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کی وجہ سے تمہاری قوم مجبور ہو جائے گی کہ وہ تم سے بھی اپنے تعلقات منقطع کر لے.بتاؤ دنیوی نقطہ نگاہ سے اس سے زیادہ منصفانہ تجویز اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ظاہری شکل میں منصفانہ اور عادلانہ اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی تھی یاکم سے کم میں نے دنیا کے پردہ پر اس قسم کی اور کوئی مثال نہیں دیکھی.چچا نے ان کی باتیں سنیں اور سمجھا کہ قوم نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے اس سے زیادہ وہ کیا قربانی کر سکتی ہے.چنانچہ جب قوم کا نمائندہ وفد یہ پیشکش کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو اس نے اس اُمّیؐ،
Page 499
وادیٔ غیر ذی زرع میں رہنے والے اور ایک غیر متمدّن ملک میں پرورش پانے والے بھتیجے کو بلایا اور اس سے کہا اے میرے بھتیجے! تجھے معلوم ہے کہ میری قوم میرا کتنا لحاظ کرتی ہے آج وہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے تیری خاطر اب تک تیرے بھتیجے کو چھوڑ رکھا ہے اسے کوئی سزا نہیں دی ( در اصل ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اتنی سزا نہیں دی جس سے وہ ختم ہو جائے ورنہ سزا تو وہ دیتے رہتے تھے)مگر اب معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی کسی طرح ختم ہو جائے.چنانچہ اے میرے بھتیجے آج انہوں نے یہ یہ تجویزیں میرے سامنے رکھی تھیں جن کا میںکوئی جواب نہیں دے سکا.میری قوم مجھے کہہ گئی ہے کہ تیرا بھتیجا ان میں سے جس تجویز کو چا ہے مان لے ہم اس پر راضی ہیں اور اگر وہ کسی تجویز کو نہ مانے تو پھر تُو اس کا ساتھ چھوڑ دے کیونکہ وہ غیر معقولیت پر قائم ہے اور بلا وجہ ضد کرتا ہے اور اگر تو اس کے بعد بھی اپنے بھتیجے کو نہ چھوڑے تو ہم مجبورہو جائیں گے کہ تیری سیادت سے انکار کر دیں اور تجھے اپنی لیڈری سے الگ کر دیں(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام مباداۃ رسول اللہ قومہ وماکان منہ).چچا یعنی ابوطالب نے جب یہ کہا تو اس خیال سے کہ میں نے ساری عمر جس قوم کی خدمت کی ہے وہ بھی آج مجھے چھوڑنے کے لئے تیار ہو گئی ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے تب ان کے بھتیجے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی یہ حالت دیکھی تو پرانی محبت اور تعلقات کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور آپ نے فرمایا اے میرے چچا میں آپ سے یہ قربانی نہیں چاہتا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیں.اے چچا آپ اپنی قوم کے ساتھ مل جائیں اور اسے خوش رکھیں.باقی رہا ان کی تجاویز سو میں نے جو کچھ اپنی قوم کے سامنے پیش کیا ہے سچ سمجھ کر کیا ہے کسی دنیوی لالچ یا حرص کی وجہ سے نہیں کیا.اور یہ تجویزیں تو کچھ چیز ہی نہیں.اے میرے چچا اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لا کر کھڑا کر دیں تب بھی میں اس سچائی کونہیں چھوڑ سکتا جو خدا نے مجھے عطا فرمائی ہے اور جس کے پیش کرنے کا اس نے مجھے حکم دیا ہے.باقی میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری خاطر کوئی قربانی کریں آپ اپنی قوم کے ساتھ جاملیں اور مجھے میرے خدا پر چھوڑ دیں.ا بو طالب اپنی قوم میں بہت بڑی وجاہت رکھتے تھے، ابو طالب اپنی قوم کے لیڈر سمجھے جاتے تھے ابو طالب اپنی قوم کی لیڈری چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے مگر جب انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو ان کے دل پر اس کا ایسا غیر معمولی اثر ہوا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو چیز اس انسان کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے یہ کسی بناوٹ سے تعلق نہیں رکھتی یہ فکر و تدبیر سے تعلق رکھنے والی بات نہیں بلکہ یہ کچھ اور بات ہے جس نے ایک ایسا گہرا نقش اس کے دل پر پیدا کر لیا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اسے اپنے مقام سے ہلا نہیں سکتی اور سچ کی خاطر یہ ہر موت قبول کرنے کے
Page 500
لئے تیار ہے.تب جس طرح آگ کے پاس بیٹھنے والا گرم ہو جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ایمان کی چنگاری سے ابو طالب کا دل بھی گرم ہو گیا اور اس نے کہا اے میرے بھتیجے جا اور اپنے کام میں مشغول رہ.میری قوم اگر مجھے چھوڑتی ہے تو بے شک چھوڑ دے میں تجھے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں کیا دنیا کے فلسفیوں میں اس قسم کی کوئی مثال مل سکتی ہے جس میں یہ سارےکونے موجود ہوں.یوں نہیں کہ فلاں فلسفی مارا گیا بلکہ ایسی مثال جس میں اس واقعہ کی طرح ہر قسم کی پیشکش کی گئی ہو اور وہ پھر بھی اپنے دعویٰ پر قائم رہا ہو.یقیناً یورپ کے کسی فلسفی میں تم ایسی مثال تلاش نہیں کر سکتے.لیکن اسلام میں تمہیں ایسی ہزاروں مثالیں دکھائی دیں گی.صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے غلاموں اور ان کے چاکروں میں بھی حضرت عمر ؓ یا حضرت عثمان ؓ کے زمانہ میں ایک بدوی سے قتل ہو گیا اور اس کا مقدمہ قاضی کے سامنے پیش ہوا قتل ثابت تھا اس لئے فیصلہ ہوا کہ اسے قتل کی سزا دی جائے.اس نے قاضی کو کہا کہ میرے پاس کچھ یتیموں کا مال پڑا ہوا ہے میں تو بے شک قتل کا سزا وار ہوں مگر میرے مرنے سے وہ یتیم بھی مر جائیں گے میں نے ان کا مال زمین میں ایک مقام پر دفن کیا ہوا ہے اور میرے سوا اس کا کسی کو علم نہیں مجھے تین دن کی اجازت دیجئے تاکہ میں جا کر وہ مال ان یتیموں کے حوالے کر آؤں.قاضی نے کہا میں اجازت تو دے دوں مگر تمہارا ضامن کون ہے ہمیں کیا پتہ ہے تم واپس بھی آؤ گے یا نہیں ؟ جنگلوں میں جو قومیں بستی ہیں ان کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہو تا ہے اس لئے قاضی نے ضامن کا مطالبہ کیا.اس نے ادھر ادھر دیکھا اور حضرت ابو ذر غفاری ؓ پر نظر ڈال کر کہا یہ میرے ضامن ہیں.قاضی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس کی ضمانت دینے کے لئے تیار ہیں ؟ انہوں نے کہا ہاں.چنانچہ اسے چھوڑ دیا گیا اور وہ چلا گیا.جب تیسرادن آیا تو عصر کے وقت اس کا انتظار کیا جانے لگا.سورج غروب ہو نے میں دو گھنٹے رہتے تھے.پون گھنٹہ گذرا مگر وہ نہ آیا.جب وقت گذرنے لگااور اس بدوی کا کچھ پتہ نہ لگا تو حضرت ابو ذر غفاری ؓ جو ایک مخلص صحابی تھے ان کی جان خطرہ میں دیکھ کر مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت ابو ذر غفاریؓ سے پوچھا کہ حضرت وہ کون شخص تھا جس کی آپ نے ضمانت دی تھی وقت ختم ہو نے کو آیا ہے اور اس کا کچھ پتہ ہی نہیں لگتا.انہوں نے جواب میں کہا مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ کون تھا.لوگوں نے ان سے کہا تو پھر آ پ نے ایک نامعلوم شخص کی اتنی بڑی ضمانت کیوں دی ؟ حضرت ابو ذر غفاری ؓ نے فرمایا اس نے جب سب لوگوں پر نظر ڈال کر میرے متعلق کہا کہ یہ میرے ضامن ہیں تو میری غیرت نے برداشت نہ کیا کہ ایک مسلمان نے جب بغیر جانے کے مجھ پر اعتبار کیا ہے تو میں اس پر اعتبار نہ کروں.وہ بھی مجھے نہیں جانتا تھا مگر جب اس نے مجھ پر یہ حسن ظنی کی کہ میں اس کی ضمانت دے دوں گا تو میںا س پر
Page 501
حسن ظنی کیوں نہ کرتا اور اس کی ضمانت کیوں نہ دے دیتا.بہر حال وقت گذرتا جا رہا تھا اور لوگوں میں بے چینی اور اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کہ یک دم انہوں نے دور سے گرد اٹھتی دیکھی اور انہیں محسوس ہوا کہ ایک شخص بے تحاشا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا چلا آرہا ہے وہ گھوڑا اتنی تیزی سے دوڑا رہا تھا کہ جب وہ مجلس میں پہنچا تو اس کا گھوڑا گرا اور مر گیا.لوگوں نے دیکھا تو وہ وہی بدوی تھا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا.اس نے کہا میں یتیموں کا مال دے آیا ہوں اور اب میں حاضر ہوں مجھے بے شک قتل کر دیا جائے اس کی اس وفا داری اور ایمان داری کااتنا اثر ہوا کہ مقتول کے وارثوں نے کہا کہ ہم اپنا خون اس کو معاف کرتے ہیں ( اسلام میں مقتول کے وارث اگر چا ہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں ) یہ ایک مثال نہیں.درجنوں اور سینکڑوں اور ہزاروں ایسی مثالیں تاریخ اسلا م میں سے پیش کی جا سکتی ہیں.پالیٹکس کی نہیںڈپلو میسی کی نہیں جو یوروپین قومیں پیش کرتی ہیں بلکہ اس قسم کی سیدھی صاف اور سادہ مثالیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ سچ اور انصاف اور قربانی اور استقامت کیا چیزیں ہیں اور کس طرح مسلمانوں نے نڈر ہو کر ان نیکیوں پر عمل کیا ہے.مگر سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیوں عمل کیا ؟ اسی لئے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مارے بھی گئے تو کیا ہوا اگلے جہان میں ہمیں بدلہ مل جائے گا.پس اگلے جہان پر اگر یقین نہ ہو تو کامل نیکی کبھی پیدا نہیں ہو سکتی.اگلے جہان پر ایمان ہی ہے جو اس صداقت کو ظاہر کرتا ہے کہ آخر نیک اعمال ہی کی فتح ہو تی ہے.(۴) دین کے ایک معنی اَلسُّلْطَانُ وَالْمُلْکُ وَالْـحُکْمُ کے ہیں.یعنی حکومت اور بادشاہت.مگر حکومت اور بادشاہت سے آج کل کی حکومت اور بادشاہت مراد نہیں جسے آئینی بادشاہت کہتے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے ذریعہ سے چلتی ہے بلکہ اس سےوہ حکومت اور ملوکیت مراد ہے جو اقتدار رکھتی ہے.اَلسُّلْطَانُ وَالْمُلْکُ وَ الْـحُکْمُ کےیہ بھی معنے نہیں کہ وہ حکومت جو ڈنڈے کے زور سے چلتی ہے اور جس میں جبر اور تشدّد سے احکام منوائے جاتے ہیں.پس جس طرح ان معنوں میں سے وہ حکومت نکل جاتی ہے جو پارلیمنٹری ہو تی ہے اور لوگوں کے مشورہ سے چلتی ہے اسی طرح اَلسُّلْطَانُ وَالْمُلْکُ وَ الْـحُکْمُ میں سے وہ حکومت بھی نکل جاتی ہے جو ڈنڈے کے زور سے چلتی ہے اور زبر دستی اپنے احکام لوگوں سے منواتی ہے.سُلْطَان کا لفظ ان حکومتوں کو بھی نکال دیتا ہے جس کے حکمران صرف رسمی بادشاہ ہوتے ہیں اور جن کا کام صرف کاغذات پر دستخط کرنا ہو تا ہے اور حُکْم کا لفظ ان حکومتوں کو نکال دیتا ہے جو ڈنڈے کے زور سے کام کرتی ہیں.عربی زبان کی ایک خصوصیت عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے تمام الفاظ اپنے اندر گہری حکمت رکھتے ہیں.مثلاً مُلْک کا لفظ ہی لے لو.ہماری زبان میں لوگ مُلک کا لفظ عام طور پر استعمال کرتے ہیں مگر جب ان
Page 502
سے پو چھا جائے کہ ملک کسے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اسی علاقہ کو جس میں ہم بستے ہیں لیکن اہل عرب اور وہ لوگ جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں وہ اس کے یہ معنے نہیں لیں گے بلکہ وہ م، ل اور ک کے مجموعہ سے اس کے معنے اخذ کریں گے.در اصل عربی زبان کو جو خصوصیتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حرفوں سے بنی ہے.میرا یہ مطلب نہیں کہ باقی زبانیں حرفوں سے نہیں بنیں.بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ باقی زبانوں کے حروف اتفاقی حادثہ ہیں مگر عربی زبان کے حروف اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ تمام حروف اپنے اندر مستقل معنے رکھتے ہیں اور ان کے مجموعہ کے معنے ان حروف سے پیدا ہو تے ہیں.گویا اپنی ذات میں کوئی ملا جلا لفظ معنے نہیں دیتا بلکہ تمام حروف مل کر معنے پیدا کرتے ہیں دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ عربی زبان کی نسبت باقی زبانوں سے وہی ہے جو دنیا کی دوسری زبانوں کو چینی زبان سے ہے.چینی زبان میں ہر جملہ ایک حرف سمجھا جاتا ہے اور ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لئے بنے بنائے جملےاستعمال ہو تے ہیں.مثلاً اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں ’’گھوڑا لاؤ‘‘ تو یہ ایک مستقل جملہ ہوتا ہے اور جب ہمیں ضرورت محسوس ہو تی ہے ہم اسی میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دیتے ہیں مثلاً ہم کہہ دہتے ہیں گھوڑا لائے.کبھی کہہ دیتے ہیں گھوڑا لایا.کبھی کہہ دیتے ہیں گھوڑا لائیں.گویا تبدیلی صرف فعل میں واقعہ ہوتی ہے.مگر چینی زبان میں گھوڑا لاؤ ایک مستقل حرف ہو تا ہے.گویا چینی زبان میں جملہ اپنی ذات میں لفظ کا قائم مقام ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تو صرف چھبیس حروف ِ تہجی ہو تے ہیں مگر ان کے ہاں کئی ہزار حروف ِ تہجی ہیں کیونکہ جب ایک مستقل جملہ کو حرف بنا یا جائے گا تو سیدھی بات ہے کہ اس طرح حروف ہزارو ں ہزار بنتے چلے جائیں گے.پس عربی اور چینی میں یہ فرق ہے کہ چینی زبان میں جملہ حرف بن جاتا ہے اور عربی زبان میں حرف لفظ کا کام دیتا ہے معنے صرف لفظ سے شروع نہیں ہو تے بلکہ حرف سے شروع ہو تے ہیں.چنانچہ ملک کے لفظ میں م ل ک کے ملنے کے بعد معنے پیدا نہیں ہو ئے بلکہ م کےبھی معنی ہیں ل کےبھی معنی ہیں اور ک کے بھی معنے ہیں اور جب یہ حروف کہیں جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک خاص معنے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے ان حروف کو خواہ آگے کرو خواہ پیچھے ایک خاص مفہوم ان تمام الفاظ میں مشترک پایا جائے گا.چنانچہ عربی زبان کے وہ تما م الفاظ جو م ل اور ک سے مرکب ہیں ان کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان میں طاقت اور قوت کے معنے پائے جائیں گے مثلاً مُلْک حکومت بادشاہت اور طاقت کو کہتے ہیں مَلِک بادشاہ کو کہتے ہیں مَلَک فرشتے کو کہتے ہیں.اس کو الٹا دو تو کَلْمٌ بن جائے گا جس کے معنے زخم کرنے کے ہیں اس میں بھی طاقت کی ضرورت ہو تی ہے.لَکْمٌ تھپڑ مارنے کو کہتے ہیں اس میں بھی طاقت کے معنے پائے جاتے ہیں غرض م ل ک سے جو الفاظ بھی
Page 503
مرکب ہوں گے ان میں طاقت اور قوت کے معنے پائے جائیں گے.یہ ایک ایسا عجیب مضمون ہے کہ اس سے سینکڑوں معانی قرآن کریم کے اور سینکڑوں معانی احادیث کے میں نے نئے نکالے ہیں.افسوس ہے کہ آخری زمانہ میں عربوں میں سے بھی یہ مضمون مٹ گیا تھا.اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی زبان کو اُمُّ الالسنہ ثابت کرتے ہوئے پھر اس مضمون پر روشنی ڈالی اور اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے لئے گویا چودہ طبق روشن ہو گئے ہیں.ہزاروں ہزار مضامین اس ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولے ہیں اور وہ مضامین ایسے ہیں کہ بعض دفعہ عرب بھی ان کو سن کر حیران رہ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کہا ں سے نکالی ہیں.میرا یہ مطلب نہیں کہ اس علم کی بنیاد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے رکھی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد نہیں رکھی بلکہ اس مضمون کی تکمیل فرمائی ہے.اس کی بنیاد ابتدا ئے اسلام میں رکھی گئی تھی.چنانچہ علامہ سکاکی نے بھی اپنی کتاب مفتاح العلوم میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے.اسی طرح ابن فارس نے بھی مخصّص میں اس پر بحث کی ہے.ابن جنّی اور ثعلبی وغیرہ نےبھی اس طرف اشارات کئے ہیں مگر ان لوگوں نے اس مضمون کو مکمل نہیں کیا صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ایک ایسے وجود ہیں جنہوں نے موجودہ زمانہ میں اس مضمون کو وسیع کیا اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے.حُکْم کا لفظ جو ح ک م سے مرکب ہے یہ بھی خالی زور پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس زور کے پیچھے کوئی معقول وجہ کام کر رہی ہو.اسی سے حکمت کا لفظ نکلا ہے جس کے معنے فلاسفی کے ہیں گویا کوئی مقصد تھا.کوئی غرض تھی کوئی فائدہ اور نفع مدّ ِنظر تھا جس کی وجہ سے ایک ہدایت دی گئی.یوں ہی حُکْم کا لفظ نہیں بولیں گے اور اگر بولیں گے تو غلط ہو گا.جیسے روٹی کو کوئی سوٹی کہہ دے تو وہ غلط ہو گا.بہر حال ح ک م اپنے اندر حکمت کےمعنے رکھتے ہیں یعنی کام کے پیچھے کوئی غرض ہو نی چاہیے کوئی نفع بخش باعث ہو نا چاہیے یوں ہی زور اور جبر اور تشدد کے ساتھ کام نہیں لینا چا ہئے.غرض اَلسُّلْطَانُ وَالْمُلْکُ وَ الْـحُکْمُ میں سے وہ آئینی بادشاہت بھی نکل گئی جس میں بادشاہ محض دکھاوے کی چیز ہو تا ہے کوئی طاقت اس میں نہیں ہو تی.دستخط کے لئے کاغذات اس کے پاس بھیج دیئے جاتے ہیں اور وہ ان پر دستخط کر کے واپس کر دیتا ہےاور جب وزراء سے پو چھا جائے کہ ایسے بادشاہ کا فائدہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عوام الناس الّو ہو تے ہیں ان کے لئے کوئی نہ کوئی بادشاہ بھی چاہیے جس کے ساتھ وہ چمٹے چلے جائیں ورنہ ہزاروں ہزار ایسے لوگ نکل آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم پارلیمنٹ کی نہیں مانتے ہم بادشاہ کی بات مانیں گے.ایسے بے وقوفوں سے چھٹکارا پا نے کے لئے بادشاہت کا ڈھونگ رچایا جا تا ہے ورنہ حقیقتاً
Page 504
اس بادشاہ میں کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ ویسا ہی ہو تا ہے جیسے کسی گڑیا کو بادشاہ سمجھ لیا جائے.اس کے مقابلہ میں ایسے بادشاہ بھی ہوتے ہیں جو حکم دے دیتے ہیں کہ فلاں کو مار دو، فلاں کو جلا دو، فلاں کو پھانسی دے دو اور جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری مرضی.حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان کو جب ہم الہامی مانتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس زبان کے پیچھے جو محرکات کام کر رہے ہیں وہ بھی مذہبی اور الہامی ہیں.اس نقطہ نگاہ کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے حکومت کا وہ مفہوم جو اسلام کے نزدیک ہے وہ ان تینوں الفاظ کوملانے سے پیدا ہو تا ہے.لغت والوںکا قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی لفظ کے معنے بیان کرتے وقت درمیان میں واؤ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ ان میں سے ہر معنے اپنی ذات میں نامکمل ہیں ہاں اگر سب معنوں کو ملا لیا جائے تب ا س کے صحیح معنے پیدا ہوں گے.اگر لغت والوں نے یہ کہنا ہو تا کہ دین کے معنے یا سلطان کے ہیں یا ملک کے ہیں یا حکم کے ہیں تو وہ کہتے اَلسُّلْطَانُ اَوِالْمُلْکُ اَوِالْـحُکْمُ مگر انہوں نے کہا ہے اَلسُّلْطَانُ وَ الْمُلْکُ وَ الْـحُکْمُ پس لغت کے قاعدہ کے مطابق یہ تینوں مل کر دین کے معنے دیتے ہیں.سُلْطَان نے تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ ہم اس حکومت کی طرف اشارہ نہیں کر رہے جو رسمی ہو تی ہے اور جو محض دکھلاوے کے طور پرکام کر رہی ہو تی ہے اور حکم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس کے احکام بلا وجہ نہیں ہوتے بلکہ اس کے ہر حکم کے پیچھے کوئی معقول وجہ ہو تی ہے کوئی اعلیٰ درجہ کی حکمت کام کر رہی ہو تی ہے.اور کوئی ضروری محرک اس کے پیچھے پو شیدہ ہو تا ہے اور مُلْک نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کا غلبہ وسیع ہے.گویا سُلْطَان نے اس کی گہرائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور مُلْک نے اس کی وسعت کی طرف اشارہ کیا ہے اور حُکْم نے اس کی معقولیت کی طرف اشارہ کیا ہے.گویا حکومت ہو اور بڑی گہری حکومت ہو، حکومت ہو اور بڑی وسیع حکومت ہو، حکومت ہو اور بڑی معقول حکومت ہو.جس کا کوئی حکم بلا وجہ نہ ہو، جس کا کوئی حکم بلاغرض نہ ہو، جس کا کوئی حکم جبری نہ ہواور اس میں ان لوگوں کا فائدہ مدّ ِنظر ہو جن کو وہ حکم دیا گیا ہو.دیکھو یہ حکومت کی کتنی زبر دست تعریف ہے اور کیسی اعلیٰ درجہ کی حکومت کا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ ایسی حکومت دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی.لیکن فرض کرو ایسی حکومت قائم ہو جائے تو تم بتاؤ کہ کیا اس سے بہتر حکومت دنیا میںکوئی اور ہو سکتی ہے ؟ حکومت بڑی گہری ہو، حکومت بڑی وسیع ہو، اس کے احکام میں وسعت بھی ہو اور گہرائی بھی ہو، ہر ضروری حکم نافذ کر رہی ہواور ساتھ ہی کوئی حکم بلا وجہ نہ ہو، غیر معقول نہ ہو، جبری نہ ہو، ہر حکم میں لوگوں کا فائدہ اور نفع مدّ ِنظر ہو.
Page 505
یہ حکومت اگر پیش کی جائے تو دنیا میں سوائے پاگل اور ضدی کے اور کون اس کا انکار کر سکتا ہے.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ مجھے بتاؤ تو سہی کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جو ایسی حکومت کا منکر ہو.حکومت کا اگر منکر ہو جائے تو بےشک ہو جائے غلبہ کا اگر منکر ہوجائے تو بے شک ہوجائے مگر جس حکومت میں یہ تین باتیں پائی جائیں اس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا.اور اگر کوئی ہو تو فَذٰلِکَ الَّذِیْ یَدُعُّ الْیَتِیْمَ وہ شخص بڑا ہی بے دین ہو گا اور اس کے اخلاق سخت خراب ہوں گے.اس کے مقابلہ میں جو شخص اس حکومت کوماننے والاہوگا اس کے اخلاق مضبوط ہو ں گے اور ا سے اپنے اعمال پر تصرّف حاصل ہوگا.یہی وہ چیز ہے جسے اسلامی اصطلاح میں حکومت الٰہیہ کہتے ہیں.مگر یاد رکھنا چاہیے اس سے وہ حکومتِ الٰہیہ مراد نہیں جس کا آج کل شور مچایا جا رہا ہے.چھوٹے لڑکے جب آپس میں کھیلتے ہیں تو بعض دفعہ ایک لڑکا جھک جاتا ہے اور دوسرا لڑکا اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاتا ہے مگر سیدھا نہیں بلکہ الٹا.جس طرح سکاٹس ایملشن پر مچھلی کی تصویر ہو تی ہے.اس کے بعد وہ لڑکا جو نیچے ہو تا ہے کہتا ہے’’ میرے کوٹھے کون چڑھیا ‘‘.دوسرا کہتا ہے ’’کانٹو‘‘ اس پر وہ کہتا ہے ’’اُتّر کانٹو میں چڑھاں‘‘ چنانچہ وہ اتر کر نیچے آجاتا ہے اور وہ لڑکاجو نیچے ہو تا ہے اوپر سوار ہو جاتا ہے.یہی حال ان حکومت الٰہیہ کا مطالبہ کرنے والوں کا ہے نہ حکومت الٰہیہ ہے نہ کچھ اور محض لوگوں میں شہرت حاصل کرنے اور وزارتوں پر قبضہ کرنے کے لئے اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے.حکومت الٰہیہ تو محض خدا تعالیٰ کی قائم کردہ ہو تی ہے بندے کی قائم کردہ نہیں ہو تی.آخر کون سا انسان ہے جو اس قسم کی حکومت کو نافذ کر سکتا ہے.سوائے اس کے جو یہ کہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ دنیا میں حکومت الٰہیہ کو قائم کروں.پھر حکومت الٰہیہ کسی ایک ملک پر نہیں ہو سکتی.حکومت الٰہیہ جب بھی آئے گی ملکی حدبندی سے آزاد ہو کر آئےگی.یہی وجہ ہے کہ میں نے اس بات کو بار بار پیش کیا ہے کہ پاکستان میںاس وقت آئین اسلام جاری نہیں ہو سکتا.لیکن میں نے جب بھی کسی لیکچرمیں یہ بات بیان کی ہے فوراً اخبارات میں شور مچ جاتا ہے کہ ایک مذہبی آدمی ہو کر شریعت کی مخالفت کی جارہی ہے.حالانکہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ شریعت اسلام پاکستان میں جاری نہیں ہو سکتی میں جو کچھ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت آئین اسلام جاری نہیں کیا جا سکتا اور شریعت اسلام اور آئین اسلام میں فرق ہے.آئین اسلام خلافت سے تعلق رکھتا ہے.اور خلافت کے معنے یہ ہیں کہ سارے مسلمان اس کے تابع ہو جائیں.اب سوال یہ ہے کہ کیا عرب پاکستان کے تابع ہو جائے گا ؟ کیا فلسطین پاکستا ن کے تابع ہوجائےگا؟ کیا انڈونیشیا پاکستان کے تابع ہوجائے گا؟ کیا اور اسلامی ممالک پاکستان کے تابع ہوجائیں گے ؟ وہ ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی خلافت نہیں اور چونکہ وہ پاکستان کے تابع نہیں ہو سکتے اس لئے پاکستان میں
Page 506
آئین اسلام بھی جاری نہیں ہو سکتا.ہاں شریعت اسلام ہر وقت جاری ہو سکتی ہے.حکوت الٰہیہ در اصل عرش پر ہے دنیا میں صرف اس کا.ظلّ قائم ہو تا ہے اور قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے کہ ہر حملہ جو اس حکومت پر ہو گا ہم پر ہو گا اور ہر دشمن جو اس پر چڑھائی کرے گا وہ ہمارا دشمن ہو گا اور ہم خود اس کا مقابلہ کریں گے.ایسی حکومت کوئی انسان بنا ہی کس طرح سکتا ہے؟ جس چیز کا میں مخالف ہوں وہ یہ ہےکہ مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم آئین اسلام جاری کریں گے کیونکہ آئینِ اسلام خلافت کے بغیر نا فذ نہیں ہو سکتا.آئینِ اسلام چند اصول کا نام ہے جو خلافت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن مسلمان اس وقت خلافت کے قائل نہیں یہ خلافت جب بھی قائم ہو گی روحانی ہو گی جیسے میں اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ میری خلافت سے دنیوی خلافت مراد نہیں.پھر میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ ہی خلیفہ بن گیا ہوں بلکہ میں ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے خلیفہ بنایا ہے.اب یہ واضح بات ہے کہ اگر میں اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو خدا خود مجھے سزا دے گا اور اگر سچا ہوں تو لوگوں کی مخالفت میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی.بہرحال نظام خلافت کے بغیر حکومت الٰہیہ دنیا میں ہر گز قائم نہیں ہو سکتی.لیکن اگر یہ حکومت قائم ہو جائے تو پھر اس سے بہتر حکومت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی.اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا حکومت الٰہیہ کے منکر کو تم نے دیکھا ہے.ایسا انسان کبھی بھی اعلیٰ درجہ کی اخلاقی زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ رذائل میں گرفتار رہتا ہےاور نفسی نفسی کے جذبات سے متاثر ہو تا ہے.غرض خدا تعالیٰ کی حکومت کا اس دنیا میں موجود ہونا اور اس کے متعلق کامل یقین رکھنا ایک بہت بڑا اور اہم عقیدہ ہے.یہ عقیدہ نہ لفظوں سے پیدا ہوتا ہے نہ تقریروں سے بلکہ یہ انسان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے.خدا تعالیٰ کی حکومت کے آخر کیا معنےہیں.کیا عیسائی خدا کو نہیں مانتے ؟ کیا یہودی خدا کو نہیں مانتے ؟ پھر خدا تعالیٰ کی حکومت کے قیام کا کیا مطلب ہے ؟ در اصل خدا تعالیٰ کی حکومت کے معنے خدا تعالیٰ کے اس دنیامیں کامل تصرف کے ہیں یعنی انسان خدا تعالیٰ کو ایک عامل اور فعّال وجود تسلیم کرے.صرف منہ سے نہ کہے کہ خدا ہے بلکہ تسلیم کرے کہ خدا اس دنیا کے ذرہ ذرہ میں دخل دے رہا ہے.مگر اس کے بھی وہ معنے نہیں جو نادان مسلمانوں نے تقدیر کے سمجھ لئے ہیں کہ اگر چوری بھی کرواتا ہے تو نعوذباللہ خدا کرواتا ہے ،بدکاری بھی کرواتا ہے تو خدا کرواتا ہے، قتل بھی کرواتا ہے تو خدا کرواتا ہے.یہ بد ترین تمسخر اور استہزاء ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کیاجاتا ہے.دنیا میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کاموں میں دخل دیتا ہے ایک حکومت چل رہی ہو تی ہے اور کوئی مقتدر بادشاہ بر سر حکومت ہو تا ہے تو کہنے والے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ سارے کام یہی کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہو تا ہے کہ ملک کے استحکام اور فوجوں کی ضروریات سے تعلق رکھنے والے تمام امور ان کے ہاتھ میں ہیں.اب اگر
Page 507
کوئی شخص یہ فقرہ کہے اور دوسرا سن کر کہہ دے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے.پاخانہ تو چوڑھا صاف کرتا ہے تو سب لوگ ہنس پڑیں گے اور کہنے والے کو پاگل قرار دیں گے.اسی طرح ہم جب زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کا ذکر کررہے ہو تے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کام وہ کرتا ہے تو اس میں چوری اور بدکاری کا کیا ذکر ہے کہ یہ کہا جائے کہ خدا ہم سے چوری کرواتا ہے، خدا ہم سے بدکاری کرواتا ہے، خدا ہم سے ظلم کرواتا ہے، خدا ہم سے بد دیانتی کرواتا ہے.اس سے زیادہ بے شرمی اور بے حیائی اور کیا ہو گی.اور پھر نام اس کا تقدیر رکھا جاتا ہے.حالانکہ یہ اوّل درجہ کی بے دینی اور کفر ہے.وہ احمق اور نادان لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر خدا کچھ کرے گا تو کفر چھڑوائے گا یا کفر کروائے گا، بےدینی چھڑوائے گا یا بے دینی کروائے گا، چوری کروائے گا یا چوری چھڑوائے گا ؟ ایک شریف آدمی اگر کسی کام میں دخل دیا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا وہ چوری کرواتا ہے یا چوری کرنے سے روکتا ہے؟ قتل کرواتا ہے یا قتل کرنے سے روکتا ہے ؟ اگر ان کے متعلق یہ بات کہی جائے کہ انہوں نے فلاں جگہ چوری کروائی ہے تو وہ لال لال آنکھیں نکال کر آ جائیں گے کہ تم نے ہماری ہتک کی ہے مگر خالقِ کون ومکان اور تمام نیکیوں کے سرچشمہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہم سے ڈاکاڈلواتا ہے، وہ ہم سے فریب کرواتا ہے اور پھر اس قسم کا عقیدہ رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے بھی یہی تعلیم پیش کی ہے.نعوذباللہ من ذالک.اس قسم کی پاک اور بے عیب کتاب کی طرف اتنا گندہ اور ناپاک عقیدہ منسوب کرنا اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا بتاتا ہے کہ مسلمان کس حد تک گر چکے ہیں اور وہ کیسے بے دین ہو گئے ہیں.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ اگر ہم نے جبراً لوگوں کو کسی بات پر قائم کرنا ہو تا تو ہم ان کو توحید پر قائم کرتے.پھر حدیثیں سناتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میںہو نا ہے وہ خدا نے پہلے سے لکھ رکھا ہے اور اس کے قلم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے(بخاری کتاب القدر باب جف القلم علی علم اللہ ).وہ اتنا غور نہیں کرتے کہ جس چیز سے خدا کی خدائی پر حرف آتا ہے اسے ہم قرآن اور حدیث کی طرف منسوب ہی کس طرح کرسکتے ہیں.خصوصاً ایسا عقیدہ جو اسلام کی اہم تعلیموں کے خلاف ہے، جو قرآن کے خلاف ہے اس کو تقدیر کے نام سے پیش کرنا اتنا گھناؤنا اور گندہ فعل ہے کہ کوئی عقلمند اور باغیرت مومن اسے ایک لحظہ کے لئے بھی برداشت نہیں کرسکتا.اس قسم کی تقدیر کوئی تقدیر نہیں.یہ ایک ڈاکو کی تقدیر تو ہو سکتی ہے مگر ہمارے پاک خدا کی تقدیر نہیں ہو سکتی ہمارے پاک خدا کی تقدیر دنیا کو پاک کرنے کے لئے جاری ہے نہ کہ اس کو ناپاک اور گندہ کرنے کے لئے.ہم جب کہتے ہیں کہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا تو اس کا وہ مفہوم نہیں ہو تا جو مسلمان سمجھتے ہیں بلکہ اس کے معنے مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ کے ہو تے ہیں یعنی تمام نتائج خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے.حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بے کار نہیں
Page 508
بیٹھا ہوا.یہ نہیں کہ تم چوری کرو اور وہ عرش پر خاموش بیٹھا رہے.بلکہ کوئی جرم اور کوئی فعل ایسا نہیں جس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو، خواہ وہ جلد نکلے یاد یر سے.کہتے ہیں خدا کی لاٹھی نظر نہیں آتی مگر جب پڑتی ہے تو اس کی چوٹ بڑی سخت ہو تی ہے.پس تقدیر کا صرف اتنا مفہوم ہے کہ ہمارا خدا چپ کر کے بیٹھا ہوا نہیں بلکہ وہ تمام افعال کے نتائج پیدا کرتا رہتا ہے جو لوگ بھی خدا تعالیٰ کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے دنیا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے رہا ان کے عمل اور خیالات پر مذہب کا کوئی اثر نہیں ہوتا.وہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے نعوذباللہ من ذالک یوں ہی ایک بڑمار دی ہے کہ یوں کرو تو اس کےیہ نتائج پیدا ہو ں گے.ورنہ وہ دنیا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے رہا، جو کچھ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اللہ میاں صرف عرش پر بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے کہ خوب تماشا ہو رہا ہے.لیکن ہم اس قسم کے خدا کے قائل نہیں.ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کاموں میں دلچسپی لے رہا ہے اور ہر کام کے نیک یا بد نتائج پیدا کر رہا ہے.اسی کی طرف سورۃ فاتحہ کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ.مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ.جب خداجزا و سزا کا مالک ہے تو دنیا میں ہر فعل کا نتیجہ جلد یا بدیر ضرور نکلتا ہے اور اگربعض دفعہ وہ نتائج اس جہاں میں مخفی ہو تے ہیں تو اگلے جہاں میں نکل آتے ہیں.دنیا نے قرآن کریم کی اس پیش کردہ صداقت کا ایک لمبے عرصہ تک انکار کیا مگر اب چند سال ہوئے سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ ہر نطفہ جو انسان کے جسم میں سے نکلتا ہے اس پر کچھ نشانات ہو تے ہیںجو مختلف اخلاق کے قائم مقام ہو تے ہیں.کوئی نشان غصہ کا ہوتا ہے، کوئی دیانت کا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ کا ہوتا ہے، کوئی سچائی کا ہوتا ہے.فرض کرو کسی کے دادے نے یا نکڑ دادے نے جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیا تھا تو اس کے نطفہ پر جھوٹ کا ایک نشان پڑ جائے گا جو نسلاً بعد نسلٍ چلتا چلا جائے گا.اسی طرح اگر باپ دادا میں بعض نمایاں خوبیاں تھیں تو وہ خوبیاں ایک نشان کی صورت میں نطفہ میں آ جاتی ہیں.اسی طرح چلتے چلتے ہو سکتا ہے کہ چھٹی یا ساتویں پشت میںان میں سے کوئی ایک نشان ٹوٹ جائے اور وہ کیریکٹر جس کاوہ قائم مقام تھا پیدا ہو نے والے بچے میں آجائے.فرض کرو کہ وہ کیریکٹر چوری کا تھا تو بچہ بڑا ہو کر چور بن جاتا ہے اور ساراخاندان حیران رہ جاتا ہے کہ اس کا نہ باپ چور تھا نہ دادا چور تھا پھر اس میں چوری کی عادت کہاں سے آگئی.حالانکہ وہ اثر باپ دادا سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے کے آباؤ اجداد سےنطفہ کےذریعہ سے چلتا چلا آرہا تھا جو اب آکر ظاہر ہوا.نکڑ دادے میں چوری کی عادت تھی جو چھٹی یا ساتویں پشت میں آکر ظاہر ہوگئی.اسی طرح جھوٹ، دغابازی اور ظلم سب افعال ایسے ہیں جو انسانی نطفہ پر اثر کرتے ہیں اور اس پر ان اخلاق کے نشانات قائم ہو جاتے ہیں جو آئندہ نسلوں میں ظاہر ہوجاتے ہیں.انسان سمجھتا ہے کہ میرا عمل پوشیدہ ہو گیا
Page 509
حالانکہ پو شیدہ نہیں ہوا بلکہ برا بر قائم رہا ہے اور آئندہ نسل میں کسی وقت آکر ظاہر ہو جائے گا.بعض قیاس آرائیاں ہوتی ہیں لیکن یہ قیاس آرائی نہیں ایک ثابت شدہ حقیقت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا خدا اس دنیا میں ہر فعل کا نتیجہ پیدا کررہا ہے اور یہی ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے ذریعہ دنیا میں اعلیٰ درجہ کی نیکی پیدا ہو تی ہے.جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ اخلاقی اور قومی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے اور قومی اصلاح کا خیال اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور نفسی نفسی کے جذبات سے متأثر ہو جاتا ہے.حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے اسی نقطہ نگاہ کو مدّ ِنظر رکھتے ہوئے اپنے متبعین کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ اے خدا تیری بادشاہت جس طرح آسمان پر ہے اسی طرح زمین پر بھی آئے (متی باب ۶ آیت ۱۰) مسیحی اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ زمین پر بھی تیرے احکام کا غلبہ ہو حالانکہ وہ تو پہلے سے ہے.اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح آسمانی لوگ تیری حکومت کی نسبت تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جاری ہے زمینی لوگ بھی اسی طرح ماننے لگیں.درحقیقت اگر دنیا کہ لوگ خدا تعالیٰ کی بادشاہت کی نسبت یقین رکھیں کہ وہ اس دنیا میں بھی موجود ہے تو دنیا کی خرابی بالکل مٹ جائے.قَادِرٌ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ خدا پر یقین ہی انسان کو حقیقی قربانی پر آمادہ کرتا ہے.دیکھو صحابہ نے کیا کچھ قربانی کی.ان کے بیوی بچے بھی تھے مگر وہ جانتے تھے کہ ہمارا خدا زندہ ہے ہم مر جائیں گے تو وہ ان کی خبر گیری کرے گا.اگر وہ بھی مر جائیں گے تو اگلے جہان میں ہمیں بدلہ مل جائے گا.جو شخص خدا تعالیٰ کو ذرہ ذرہ کا دیکھنے والامانتا ہے وہ غریبوں پر ظلم نہیں کر سکتا وہ قوم کی غفلت پر خاموش نہیں رہ سکتا.کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ سزادے گا اور اس کا اثر اس پر بھی پڑے گا.وہ اپنی روحانی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتا.وہ دکھاوا نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا شخص اپنا بدلہ خدا سے چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ تو خود دیکھ رہا ہے دکھاوے کی کیا ضرورت ہے اور جب وہ خود نیکی کرتا ہے تو لوگوں کو نیکی سے کب روک سکتا ہے.پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا قانون گو اس دنیا میں ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا.مگر جب خدا تعالیٰ کے مامور دنیا میں آتے ہیں تو یہ قانون نہایت نمایاں رنگ اختیار کر لیتا ہے.خدا تعالیٰ ہمیشہ ہی ظالم کو سزاد یتا ہے، خدا تعالیٰ ہمیشہ ہی نیک لوگوں کو ترقی دیتا ہے.مگر جب نیک اور متقی لوگوں کی جماعت کسی مامور کے ذریعہ قائم کی جا رہی ہو تو اس وقت خدا تعالیٰ کا یہ قانون بڑے نمایاں طور پر ظاہر ہو نے لگتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب غار ثور میں جا چھپے اور حضرت ابو بکر ؓ آپؐکے ساتھ تھے تو مکہ کے کفار کا قافلہ آپ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور اس نے ایک کھوجی بھی اپنے ساتھ لے لیا.پاؤں کے نشانا ت کو دیکھتے دیکھتے آخر تمام کفار غار ثور کےمنہ پر جا پہنچے.یہ غار دو تین گز لمبی چوڑی ہے.اللہ تعالیٰ
Page 510
کی حکمت کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ؓ کے ساتھ غار ثور میں داخل ہوگئے تو مکڑی نے اس کے منہ سے نکلے ہوئے ایک درخت کی شاخوں پر جالا تن دیا.جن لوگوں نے مکڑی کو جالا تنتے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ مکڑی منٹوں میں جالا تن دیتی ہے.یہ ایک خدا ئی فعل تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ظاہر ہوا.کھوجی ساتھ تھا اس نے مکہ والوں سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اس غار میں ہیں اور کہیں نہیں گئے.وہ چاہتے تو اس وقت بڑی آسانی سے جھانک کر آپ کو دیکھ سکتے تھے مگر سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح جھانک سکتے جب کہ ایک فعّال خدا موجود تھا.خدا تعالیٰ نے اس وقت ان کی گر دنیں پکڑی ہوئی تھیں اور وہ غار کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے تھے.چنانچہ باوجود اس کے کہ وہ مکہ سے سات میل تک اپنے کھوجی کے ساتھ آئے عین غار ثور کے منہ پر پہنچ کر وہ اس کی بات نہیں مانتے اور ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا کھوجی آج پاگل ہو گیا ہے بھلا اس غار میں بھی کوئی جا سکتا ہے مکڑی نےجالا تنا ہواہے اگر کوئی اندر دا خل ہو تا تو یہ جالا ٹوٹ نہ جاتا ؟ اب دیکھ لو جہاں تک انسانی تدبیر کا سوال ہے یہ امر ناممکن تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہ آتے.اسی لئے حضرت ابوبکر ؓ اس وقت گھبرائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو کفار اتنے قریب آچکے ہیں کہ اگر وہ ذرا بھی جھک کر ہمیں جھانکیں تو دیکھ سکتے ہیں.اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا.ابوبکر غم مت کرو خدا ہمارے ساتھ ہے (الروض الانف؛ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وابوبکر فی الغار) حالانکہ وہ ابو بکر کو پکڑنے نہیں آئے تھے اگر وہ ان کو پکڑ بھی لیتے تو مار پیٹ کر چھوڑ دیتے وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہتے تھے.مگر جس شخص کو پکڑنے کے لئے وہ نہیں آئے وہ تو گھبرا تا ہے اور جس کو پکڑنے کے لئے آئے ہیں وہ بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا ان کفار میں یہ طاقت ہی کہاں ہے کہ وہ ہمیں جھانک کردیکھ سکیں.خدا ہمارے ساتھ ہے.وہ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں.بلکہ دنیا کے ذرہ ذرہ پر کامل تصرف رکھتا ہے اس پر حضرت ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے لئے تو نہیں گھبرایا مجھے پکڑ کر اگر انہوں نے مار بھی ڈالا تو کیا ہوا میری گھبراہٹ تو صرف آپ کے لئے تھی.کہ کہیں آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچے کیونکہ اگر آپ کو کوئی ضرر پہنچا تو دین تباہ ہو جائے گا.دیکھو کتنا عظیم الشان یقین تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی باد شاہت پر حاصل تھا.آپ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے منشا کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا.پھر حنین کے موقع پر جب صحابہؓ کا لشکر کفار کے تیروں کی بوچھاڑ سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے قدم اکھڑ گئے تو ایک وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا آیا جب صر ف ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گیا.اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھنا چاہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی سواری کی باگ پکڑ لی اور
Page 511
انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آگے بڑھنے کا وقت نہیں.لشکر جب تک دوبارہ جمع نہ ہو لے مناسب یہی ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش سے فرمایا.ابو بکر ؓ میرے گھوڑے کی باگ چھوڑدو.اور پھر آپ اسے ایڑ لگا کر یہ کہتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے کہ اَنَا النَّبِیُّ لَا کَذِبْ.اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.(الطبقات الکبرٰی غزوۃ رسول اللہ الی حنین) میں خدا کا نبی ہوں جھوٹا نہیں میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں یعنی جب میں خدا کا نبی ہوں اور میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وَاللّٰہُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ تو وہ خود مجھے بچائے گا.دیکھو یہ خدا تعالیٰ کے فعّال ہو نے پر ایمان کا کتنا زبردست مظاہرہ ہے.آپ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ صرف عرش پر بیٹھا ہوا نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی حکومت الٰہیہ جاری ہے.اور تیر بھی اگر چلتا ہے تو اسی کے حکم سے چلتا ہے.یہ کس طرح ہوسکتا ہےکہ چار ہزار تیر اندازوں کے تیر وں میں کوئی ایک تیر بھی مجھے خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر آلگے.تیر خدا کا غلام ہے افسر نہیں کہ وہ اس کے حکم کے خلاف کسی کے سینہ میں آ لگے.دیکھو چار ہزار تیر اندازسامنے ہیں راستہ تنگ ہے مگر آپ برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اَنَا النَّبِیُّ لَا کَذِبْ.اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ.میں خدا کا سچا نبی ہو ں جب مجھے خدا نے کہا ہے کہ یہ لوگ تجھے مار نہیں سکتے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کے تیر مجھے ہلاک کر دیں.پھر یمن کا گورنر ایران کے بادشاہ کے حکم کے ماتحت آپ کو گرفتار کرنے کے لئے اپنے آدمی بھجواتا ہے.یہودیوں نے اس کے پاس شکایت کی تھی کہ عرب میں ایک نئی حکومت بن رہی ہے جو آپ کے لئے پریشانی کا موجب ہو گی.بادشاہ بےوقوف تھا اس نے یمن کے گورنر کو پیغام بھجوایا کہ میں نےسنا ہے عرب میں ایک مدعیٔ نبوت کھڑا ہوا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے میرے پاس بھجوا دیا جائے.گورنر یمن نے اپنے آدمی مدینہ بھجوائے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے.اور انہوں نے کہاکہ اس اس طرح ہمارے بادشاہ نے گورنر یمن کے نام حکم بھیجا تھا جس پر گورنر نے ہمیں آپ کی طرف بھجوایا ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں.معلوم ہو تا ہے بادشاہ کو کوئی غلط فہمی ہوگئی ہے چنانچہ گورنر نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو یہ بھی کہہ دیں کہ میں آپ کے متعلق بادشاہ کی خدمت میں سفارش کروں گا اور اسے لکھوں گا کہ آپ کے پاس غلط رپورٹ پہنچی ہے.اس شخص سے ملک کے امن کو کوئی خطرہ نہیں.آپ نے فرمایا ٹھہرو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں.دوسرے دن وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابھی کچھ اور ٹھہرو میں دعا کر رہا ہوں.تیسرے دن وہ پھر آئے تو آپ نے فرمایاابھی کچھ اور ٹھہرو میں دعا کر رہا ہوں.چوتھے دن وہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیے.آپ نے فرمایا تم جاؤ اور گورنر سے کہہ دو کہ میرے خدا نے تمہارے خدا کو آج رات مار ڈالا ہے.
Page 512
انہوں نے کہا جناب ایک بار پھر سوچ لیجئے اس کا نتیجہ ملک عرب کے لئے اچھا نہیں ہو گا یہاں سخت تباہی واقعہ ہو گی اور عرب کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی.آپ ہمارے ساتھ چلیں گورنر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی سفارش کر دے گا.اور آپ کو کو ئی نقصان نہیں پہنچے گا.آپؐنے فرمایا جاؤ میں نے جو کچھ کہا ہے اپنے گورنر سے کہہ دو کہ میرے خدا نے آج رات تمہارے خدا کو مار دیا ہے.اس پر وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے گورنر کو یہ جواب سنا دیا.اس نےجواب سن کر یہ کہا کہ یہ شخص یا تو پاگل ہے یا پھر واقعہ میں اللہ تعالیٰ کانبی ہے کسی دوسرے کے منہ سے ایسی بات نہیں نکل سکتی.چودہ پندرہ دن گذرے تو ایک شاہی جہاز کے آنے کی اطلاع ملی گورنر نے اپنے سیکرٹری استقبال کے لئے بھیجے جب سفیر گورنر یمن کے پاس پہنچا اور ا سے خط پیش کیا تو جیسے ایرانی دستور تھا اس نے ادب کے ساتھ اس خط کو چوما.مگر جب اس کی مہر دیکھی تو چونکہ وہ دوسرے بادشاہ کی مہر تھی اس نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ بات ٹھیک معلوم ہو تی ہے جو عرب کے نبی نے کہی تھی.پھر اس نے خط کھولا تو اس کے اندر یہ الفاظ تھے جو شاہ ایران کے بیٹے کی طرف سے تھے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ حکومت کے تمام آفیسرز سے ہماری اطاعت کا عہد لو اور ہم تم کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں تاریخ کو ان ظلموں کی وجہ سے جو بادشاہ کر رہا تھا اسے مار ڈالا ہے اور اب ہم خود بادشاہ ہیں اور ضروری ہے کہ ہماری اطاعت کا عہد لیا جائے.اس کے بعد اس نے لکھا کہ ہمارے باپ نے جو ظالمانہ احکام دیئے تھے ان میں سے ایک حکم عرب کے ایک مدعیٔ نبوت کے متعلق بھی تھا کہ اسے گرفتار کر کے ہمارے پاس بھجوایا جائے ہم اس حکم کو بھی منسوخ کرتے ہیں اب اس کی تعمیل کی ضرورت نہیں.جب اس نے تاریخ دیکھی تو وہ وہی تاریخ تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے خدا نے تمہارے خدا کو آج رات مار ڈالا ہے(تاریخ الرسل والملوک ذکر خروج رسل رسول اللہ الی الملوک).اب دیکھو یہ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ خدا کا کتنا بڑا نشان ہے کہ اس نے بیٹے کے ہاتھ سے باپ کو مروا ڈالا اور کس طرح اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ دنیا کے ذرہ ذرہ پر خدا تعالیٰ کی حکومت جاری ہے.یہی وہ عقیدہ ہے جس سے دنیا میں حقیقی عدل اور انصاف قائم ہو تا ہے یہ نہ ہو تو انصاف قائم نہیں ہو سکتا.پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بتاؤ تو اس شخص کا حال جو اس دنیا میں حکومت الٰہیہ کا انکار کرتا ہے.اگر کوئی انکار کرے تو تم دیکھو گے کہ اسے کبھی سچا تقویٰ نصیب نہیں ہو گا.دنیا کے پردہ پر سچا تقویٰ سوائے خدا تعالیٰ کی بادشاہت ماننے کے اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتا.جس کو پتہ ہو گا کہ خدا دنیا کے تمام معاملات میں دخل دے رہا ہے اور ہر کام کا وہ نتیجہ پیدا کرتا ہے وہ بدی کرے گا کیوں.جتنا جتنا یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کے اندر تقویٰ بھی بڑھتا چلا جائے گا اور وہ بدیوں سے بچتا چلا جائے گا.
Page 513
دین کے پانچویں معنے مذہب کے (۵)دین کے ایک معنے مذہب کے ہیں.مذہب بھی انسان کو اخلاق فاضلہ کی تعلیم دیتا ہے.خواہ کوئی مذہب ہو.مذہب اپنی ذات میں بہت سی بدیوں کو روکنے والی چیز ہے اس میں سچے مذہب کی بھی کوئی شرط نہیں.ہر مذہب انسان کو بدیوں سے روکتا ہے.بے شک لوگ کہتے ہیں کہ آپس کی لڑائیوں اور فسادات کی بڑی وجہ مذہب ہی ہے لیکن اگر غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ لڑائیاں اور فسادات مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب پر عدم عمل کی وجہ سے ہیں.مثلاً سکھ مذہب کو ہی لے لو سکھ مذہب کی بنیاد حضرت باوانانک رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر ہے اور انہوں نے جو تعلیم دی اس میں یہی لکھا ہے کہ امن سے رہو بنی نوع انسان پر رحم کرو اور فتنہ و فساد میں حصہ نہ لو.یہی حال ہندو مذہب کا ہے.جب انسان کسی مذہب کا پیرو ہو تا ہے تو گو وہ اس کی تعلیم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فتنہ و فساد میں حصہ لینے لگ جائے مگر کبھی نہ کبھی اسے خیال آجاتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چا ہئے.عیسائی دنیا میں کتنا ظلم کر رہے ہیں پانچ سو سال تک انہوں نےدنیا کو اس طرح غلامی کے پنجہ میں دبائے رکھا ہے کہ جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی مگر انجیل میں تو یہی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تُو اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے.اور اگر کوئی تجھے ایک میل بیگار لے جانا چاہے تو تُو اس کے ساتھ دو میل چلا جا(متی باب ۵ آیت ۳۹تا ۴۱).عیسائی خواہ کتنا ظلم کریں جب کبھی کوئی عیسائی انجیل کو غور سے پڑھے گا اس کے دل میں ضرور رحم پیدا ہو گا اور اسے یہ احساس ہو گا کہ مجھے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے.ہندو مذہب کو لے لو اس میں نہایت اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم موجود ہے.میں نے خود وید پڑھے ہیں میں تو جب بھی انہیں پڑھتا ہوں مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں.اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ویدوں میں اس قسم کی لغویات بھی ہیں کہ فلاں رشی نے دھوتی اتار کر رکھی تو بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اس طرح اس لئےپیدا ہوا ہوں کہ میں گندے رستہ سے پیدا نہیں ہو نا چا ہتا تھا مگر اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی صفات کا ذکر ایسے شاندار طریق پر اس میں پایا جاتا ہے کہ اسے پڑھ کر یوں معلوم ہو تا ہے کہ انسان کا دل زمین سے اونچا ہو رہا ہے.بے شک اس میں اور چیزیں بھی مل گئیں مگر اس کا ابتدائی منبع ضرور خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا اور جو شخص بھی تعصب کو دور کر کے ویدوں کا مطالعہ کرے گا اس کا دل روحانیت کے جذبات سے لبریز ہو جائے گا.یہی حال انجیل، تورات اور ژند و اوستا کا ہے.پھر قطع نظر اس سے کہ کوئی مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا نہیں بغیر نیک تعلیم کے کوئی مذہب پھیل ہی نہیں سکتا.کیا کوئی بھی مذہب دنیا میں ایسا ہے جس کی یہ تعلیم ہو کہ فریب کرو، بدکاری کرو؟ ہندوؤں میں وام مارگی ایک ایسا فرقہ ہے جس میں بدکاری کو جائز سمجھا جاتا ہے مگر وہ مذہب نہیں بلکہ
Page 514
ایک فلسفہ ہے.وہ اپنے آپ کو کسی الٰہی کتاب کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ الٰہی کتاب کا جھوٹا ترجمہ کرتے ہیں.مثلاً وید میں لکھا ہےنیکی کر تو وہ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ بدکاری کر.مگر بہر حال یہ ایک فلسفہ ہے مذہب نہیں.مذہب کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ خدا نے مجھے یوں کہا ہے اور ایسی کوئی الہامی کتاب نہیں جس میں یہ تعلیم ہو کہ بدی کر.کوئی مذہب ایسی تعلیم دے ہی نہیں سکتا.اس لئے کہ اگر وہ ایسی تعلیم دے گا تو دنیا میں مقبول نہیں ہوسکے گا.مذہب ہمیشہ زمانہ کی رَو کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتا ہے اور جب مذہب کا کام ہی یہ ہے کہ وہ عام رَو کے خلاف تعلیم دے تو وہ خلاف فطرت تعلیم دے کر پھیل ہی کس طرح سکتا ہے؟ رسم و رواج تو اس کے پہلے سے ہی مخالف ہوتے ہیں اگر فطرت بھی اس کےخلاف ہو تو وہ چلے گا کس طرح.سچے مذہب کی مخالفت رسم و رواج و عادات بے شک کرتے ہیں اور سخت کرتے ہیں مگر چونکہ وہ فطرت اور عقل کے عین مطابق ہوتا ہے باوجود دنیا کی مخالفت کے وہ آخر جیت ہی جاتا ہے.کیونکہ فطرت و عقل اس کی تائید میں ہر انسان کے دل میں بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں.مجھے ایک دفعہ بر ما سے ایک شخص نے بہائیت کے متعلق ایک کتاب بھیجی اور لکھا کہ آپ دیکھیں بہائیت کی تعلیم کیسی اعلیٰ ہے کہ سچ بولو، عورتوں کو تعلیم دو،ظلم نہ کرو، بدی سے بچوکیا ایسی تعلیم بھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟میں نے اسے جواب میں لکھاکے یہ بڑی اچھی باتیں ہیں مگر اس سے جو نتیجہ آپ نے نکالا ہےمیں اس سے متفق نہیں.اس لئے کہ آپ کہتے ہیں یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے.بہائیت کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، بہائیت کہتی ہے عورتوں کے حقوق ادا کرو، بہائیت کہتی ہے فریب نہ کرو، بہائیت کہتی ہے امانت اور دیانت سے کام لو.میں نے لکھا کہ دنیا میں بڑے بڑے مذاہب یہودیت، اسلام، ہندومذہب اور زرتشتی ازم ہیں ان تمام مذاہب کی کتب میں سے آپ وہ حوالجات نکال کر مجھے بھجوا دیں جن میں یہ لکھا ہو کہ جھوٹ بولو، سچ نہ بولو، دیانت داری کو ترک کر دو، انصاف نہ کیا کرو، عورتوں کے حقوق نہ اداکیا کرو.اگر کسی مذہب کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہو تو میں مان لوں گا کہ بہائیت نےنہایت اعلیٰ تعلیم پیش کی ہے اور اگر سب مذاہب میں یہی تعلیم ہے تو اس میں بہائیت کو امتیاز کون سا حاصل ہوا.یہ تو ایک طبعی تعلیم ہے جو ہر مذہب کو پیش کرنی پڑتی ہے ورنہ فطرت کے خلاف کھلی تعلیم دے کر وہ کہاں کامیاب ہو سکتا ہے.غرض کسی مذہب کو لے لو وہ سچا ہو یا جھوٹا ضرور اخلاقی پابندی کراتا ہے یہی وجہ ہے قرآن کریم نے اہل کتاب کی لڑکیاں لے لینا تو جائز قرار دیا ہے لیکن غیر اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی جائز قرار نہیں دی.اسی طرح اہل کتاب کے ذبیحہ کو تو جائز قرار دیا ہے لیکن غیر اہل کتاب کے ذبیحہ کو جائز قرار نہیں دیا.اس میں حکمت یہی ہے کہ اگر ایک عیسائی عورت آئے تو
Page 515
خواہ وہ اپنے مذہب پر کس قدر ہی ناقص ایمان رکھتی ہو بہرحال انجیل کی تعلیم اس پر ضرور کچھ نہ کچھ ضبط رکھے گی.ایک یہودی عورت کو یہودی مذہب کی تعلیم بعض حدود کے اندر مقید رکھے گی.ایک ہندو عورت کو ہندومذہب کی تعلیم اباحت اور بے دینی کی طرف جانے سے روکے گی.لیکن جو عورت لامذہب ہے جو مانتی ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی کتاب دنیا کی ہدایت کے لئے نازل کی ہے وہ یقیناً ایسے کام کر سکتی ہے جو ہمارے علم سے باہر ہوں.ایک عیسائی عورت کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے کیونکہ اس کی تعلیم موجود ہے.ایک یہودی عورت کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے کیونکہ اس کی تعلیم موجود ہے.لیکن ایک لامذہب عورت کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کرے گی کیونکہ اس کی کوئی ایسی تعلیم نہیں جس کی بنا ءپر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ وہ کیا کچھ کرے گی.اسی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت قبول کی اور کھانا کھایا(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام قصۃ الشأۃ المسمومۃ).یہ الگ بات ہے کہ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا.یہ انفرادی فعل تھا کیونکہ یہودی تعلیم یہ نہیں کہتی کہ دوسرے کے کھانے میں زہر ملا دیا کرو.غرض ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بنیاد ایسی ہو نی چاہیےجس پر چلنے سے ہم محفوظ ہو جائیں اور وہ بنیاد مذہب کے سوا اور کوئی نہیں.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ.تمہیں دنیا کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ مذہب بھی بہت سی بدیوں کو روک رہا ہے چا ہے وہ جھوٹا ہو یا سچا.اگر سچا ہو گا تو نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ، وہ تو ہر قسم کی خرابیوں اور گندوں سے بچائے گا لیکن جو جھوٹا مذہب ہو وہ بھی بہت سی بدیوں سے لوگوں کو بچا لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر اخلاقی تعلیم ضرور پائی جاتی ہے.پس فرماتا ہے جو شخص مذہب کو تسلیم نہیں کرتا تم دیکھو گے کہ وہ قسم قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہوجائے گا.مذہب کو تسلیم کرنے والا اگر گناہ بھی کرے گا تو ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں یہ بھی احساس پیدا ہو گا کہ میں مذہب کے خلاف چل رہا ہوں اور میرا فعل میری غلطی کا نتیجہ ہے لیکن جو شخص کسی مذہب کو ماننے والا نہیں وہ غلطی بھی کرے گا تو کہے گا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اور یہ مقام کہ بدی کو جائز سمجھا جائے بڑا خطرناک ہو تا ہے.دین کے چھٹے معنے عبادت الٰہیہ کے (۶)دین کے چھٹے معنے عبادت الٰہیہ کے ہیں اس لحاظ سے اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ کے یہ معنے ہوں گے کہ مجھے بتا تو سہی اس شخص کا حال جو دین یعنی عبادت الٰہیہ کا انکار کرتا ہے.عبادت الٰہیہ بھی انسان کو بڑی بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے.یہ عبادت بھی خواہ سچی ہو یا جھوٹی دونوں صورتوں میں بدیوں سے روکنے والی ہو تی ہے یہ ضروری نہیں کہ سچے مذہب کی بتائی ہوئی عبادت الٰہیہ ہی بدیوں سے
Page 516
روکنے والی ہو بلکہ در حقیقت ہر عبادت الٰہیہ بدی سے روکتی ہے.چاہے ہندو کی ہو، عیسائی کی ہو،یہودی کی ہو، زرتشتی کی ہو.مثلاً عیسائی اللہ تعالیٰ سے دعا کر تا ہے تو کیا کہتا ہے یہی کہتا ہےکہ اے خدا میری آج کی روٹی مجھے دے اے خدا تیری بادشاہت جیسی آسمان پر ہے ویسی ہی زمین پر بھی آئے(متی باب ۶ آیت ۱۰،۱۱).یہ چیز انسان کے دل میں آخر خشیت تو پیدا کر دیتی ہے.ایک جابر بادشاہ جو ظالمانہ حکومت کر رہا ہو تا ہے اگر کھڑے ہو کر دن میں ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا میری آج کی رو ٹی مجھے دے تو اس کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ انکسار پیدا ہوجاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی کسی کا محتاج ہوں.اس کے بعد یہی خیال اسے نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے.غرض عبادت الٰہیہ اپنی ذات میں بڑے بڑے گناہوں کو دور کرنے والی ہو تی ہے.چنانچہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى.عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ نماز انسان کو فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے اسی مضمون کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ.مجھے بتا تو سہی کہ وہ کون ہے جو عبادت الٰہیہ کا منکر ہے.اگر ہے تو تُو دیکھے گا کہ اس میں یہ یہ عیوب ہو ں گے کہ وہ یتیموں پر ظلم کرے گا، مسکینوں کے حقوق ادا نہیں کرے گااور مداہنت اور منافقت کا مادہ اس میں پایا جائے گا.وہاں فرمایا تھا نماز بدیوں اور بےحیائیوں سے روکتی ہے اور یہاں فرماتا ہے کہ جو نماز کا منکر ہے وہ بدی کامرتکب ہو گا گو یا وہی مفہوم یہاں دوسرے الفاظ میں ادا کر دیا گیا ہے.نیکی کی صحیح تعریف عبادت الٰہیہ کیا چیز ہے اور نیکی کی صحیح تعریف کیا ہے اس بارہ میں یورپ میں بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں.یورپ کے فلاسفروں نے اس موضوع پر دو دو، تین تین، چار چار جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں اوربڑی بڑی لمبی بحثیں کرنے کے بعد انہوںنے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نیکی وہ ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے.مگر ہر تعریف جو انہوں نے کی ہے اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض پڑتا ہے.مثلاً یہی تعریف لے لو کہ نیکی وہ کام ہے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے.اگر اس کو درست سمجھ لیا جائے تو کیا اگر اکثر لوگ یہ فیصلہ کرلیں کہ ہم قلیل التعداد لوگوں کولوٹ لیں گے تو ان کا یہ فیصلہ جائز ہو گا.اس تعریف کے رو سے یقیناً اکثریت کی لوٹ مار جائز ہوگی مگر در حقیقت جائز نہیں.اسی طرح اور جس قدر تعریفیں کی جاتی ہیں سب کی سب غلط ہیں.صرف ایک تعریف ہے جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیکی کی صحیح تعریف ہے اور وہی اکیلی تعریف ہے جس کے بغیر کوئی تعریف نہیں اور وہ تعریف جس کا قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے یہ ہے کہ نیکی کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی تصویر کا انعکاس اپنے اندر لے لینے کو.تَعبُّد کے معنے ہو تے ہیں نشان لے لینا.پس عبادت الٰہیہ کے معنے ہوئے خدا تعالیٰ کے عکس اور اس کی تصویر کو اپنے اندر پیدا کر لینا.یہی ایک صحیح ترین تعریف ہے اور اس کے سوا اور کوئی تعریف نہیں.جو شخص خدا تعالیٰ کو
Page 517
نہیں مانتا اسے ہم پہلے خدا تعالیٰ کے وجود کا قائل کریں گے.لیکن جب وہ قائل ہو جائے گا تو اسے ماننا پڑے گا کہ اگر کامل اور بےعیب وجود خدا تعالیٰ کا ہے تو نیکی سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم اس بے عیب اور کامل ذات کا عکس اپنے اندر پیدا کر لیں اور اس کی تصویر بن جائیں.جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی صفات کا عکس اپنے اندر لے لے گا تو وہ تمام دنیا سے حسن سلوک کرنے لگ جائے گا اور اس کا رحم دوست اور دشمن سب پر وسیع ہو گا کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب اس کے بندے ہیں.ابو جہل بھی اس کا بندہ ہے اور محمدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بندے ہیں.یوناہ نبی کے واقعہ کو ہی دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونسؑ کو الہاماً بتایا کہ نینوہ کی بستی چالیس دنوں کے اندر اندر تباہ کردی جائے گی وہ اس بستی کو چھوڑ کر جنگل میںجا بیٹھے اور عذاب کا انتظار کرنے لگے.چالیس دن کے بعد کوئی نینوہ سے آنے والا ملا تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ نینوہ کا کیا حال ہے اس نے بتایا کہ سب لوگ خوش و خرم ہیں اور بالکل خیریت کے ساتھ ہیں.اس پر حضرت یونسؑ کو خیال گذرا کہ اگر میں نینوہ میں واپس گیا تو لوگوں کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی.چنانچہ وہ جہاز میں بیٹھ کر کسی غیر ملک کی طرف چل پڑے.راستہ میں طوفان آیا اس پر انہوں نے جہاز والوں سے اصرار سے کہاکہ یہ عذاب میری وجہ سے آرہا ہے جو اپنے آقا (خدا) کا بھاگا ہوا غلام ہوں اس لئے مجھے سمندر میں پھینک دو.چنانچہ بہت سے انکار کے بعد انہوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کی ایک بڑی مچھلی ان کو نگل گئی اور آخر اس نے قے کر کے انہیں کنارہ پر پھینک دیا وہ ابھی زندہ تھے مگر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے سخت کمزور ہو چکے تھے وہاں ایک کدو کی بیل اُگی ہوئی تھی انہوںنے اس کے سایہ میں سر چھپایا اور آرام کیا.رات کو خدا تعالیٰ نے ایک کیڑے کے دل میں القاء کیا اور اس نے راتوں رات وہ بیل کاٹ کر رکھ دی.صبح جب انہوں نے بیل کو کٹا دیکھا تو جیسے انسان کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ناراضگی کے وقت بے جان چیزوںاور جانوروں کو بھی برا بھلاکہہ دیتا ہے انہوں نے بھی غصہ میں کہا کہ خدا اس کیڑے پر لعنت کرے جس نے ایسی آرام دہ بیل کو کاٹ دیا ہے.اس پر حضرت یونسؑ کو الہام ہوا کہ اے یونس ! کیا یہ بیل تیری اگائی ہوئی تھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں.اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیل تیری اگائی ہوئی نہیں تھی صرف تجھے اس سے فائدہ پہنچ رہا تھا مگر جب یہ بیل کٹ گئی تو تجھے کتنا غصہ آیا کہ تو نے کیڑے پر بھی لعنت کر نی شروع کر دی.اے یونس اگر تجھے اس بیل کا اتنا غم ہے تو کیا نینوہ کے رہنے والے ہمارے بندے نہیں تھے وہ خواہ کتنے ہی گندے ہوں.بہر حال ہمارے بندے تھے جب انہوں نے توبہ کرلی تو تُو کس طرح یہ امید کر تا تھا کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے.یہ ہے ہمارا خدا جو نہ طرفداری کرتا ہے نہ جتھوں کا ساتھ دیتا ہے نہ طاقت ورکی تائید کرتا ہے.وہ رحم اور صرف رحم چا ہتا ہے.چنانچہ جب بھی کوئی شخص
Page 518
اس سے رحم کی استدعا کرتا ہے وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا مگر توبہ بہرحال سچی ہونی چاہیے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ كُلًّا نُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءِ وَ هٰۤؤُلَآءِ.(بنی اسـرآءیل:۲۱) ہماری بادشاہت تو یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ابو جہل کو بھی رزق دیتے ہیں.اللہ تعالیٰ کا سورج چڑھتا ہے تو جیسے ایک مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے ویسے ہی ایک کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے.یہ وہ ہستی ہے جس کی نقل کرنے کے بعدہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں.پس عبادت الٰہیہ کے معنے صرف سجدہ اور رکوع کرنے کے نہیں بلکہ اپنے سامنے ایک اعلیٰ درجہ کا نمونہ رکھ کر عبادت کرنے کے ہیں.جو اس نمونہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے وہ نہایت اعلیٰ درجہ کی زندگی بسر کرتا ہے.ظاہر ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات کو اپنے لئے نمونہ بنائے گا اس کا عمل اور نمونہ دوسرے سب لوگوں سے اچھا ہو گا.دین کے ساتویں معنے ملّۃ کے (۷) دین کے ایک معنے جیسا کہ میں نے بتایا تھا مِلَّۃ کے ہوتے ہیں.مِلَّۃ کے دو معنے ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس کو دو۲ حصوں میں تقسیم کر دیا تھا.ایک شریعت اور مذہب کے معنے.دوسرے قومیت کے.دین اور مِلّۃ میں فرق دین اور مِلَّۃ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ دینُ اللہ تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن مِلَّۃُ اللہ نہیں کہہ سکتے.کیونکہ شریعت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے مگر خدا کسی قومیت میں شامل نہیں وہ قوموں سے بالا ہے.اس لئے مِلَّۃ کے لفظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر تے.مِلَّۃ کا لفظ دین کی نسبت ان معنوں میں وسیع ہے کہ ہر دین شریعت کے لحاظ سے مِلَّۃ میںشامل ہے لیکن ہر مِلَّۃ کے مفہوم میں دین شامل نہیں لیکن دین میں ایک اور معنے بھی پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مِلَّۃ کے اس حصہ کے مشابہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ دین کے معنے خدمت کے بھی ہیں چنانچہ کہتے ہیں دَانَ الْقَوْمَ: خَدَمَھُمْ یعنی دَانَ الْقَوْمَ کے ایک معنے یہ ہوتے ہیں کہ اس نے قوم کی خدمت کی.پس چونکہ اس آیت سےاگلی آیت فَذٰلِکَ الَّذِیْ یَدُعُّ الْیَتِیْمَ ہے.اس لئے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ دین کے معنوں میں قومی خدمت بھی شامل ہے.یتیم اس شخص کا تعلق دار نہیں ہو تا اور نہ مسکین اس کا تعلق دار ہو تا ہے نہ قوم میں حسن سلوک کا مادہ پیدا کرنا جس کا وَیَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ میں ذکر آ تا ہے انسان کا شخصی معاملہ ہے.بلکہ یہ سارے اعمال قوم سے تعلق رکھتے ہیں.یتامیٰ و مساکین سے حسن سلوک بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے اور قوم سے حسن سلوک بھی قوم کی خدمت ہے.پس اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ کے ایک معنے یہ ہوں گے کہ کیا توبتا سکتا
Page 519
ہے یا مجھے بتا تو سہی اس شخص کا حال جو قومی خدمت کا منکر ہے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ اس کے اندر قومی جذبہ نہیں پایا جاتا یا قومی خدمت کا احساس اس کے دل میں نہیں پایا جاتا.اَلْکُفرُمِلَّۃٌ وَاحِدَۃٌ کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْکُفْرُ مِلَّۃٌ وَاحِدَۃٌ.(مؤطا کتاب الفرائض باب لایرث المسلم الکافر) کفر ایک ملت ہے.یہاں مِلَّۃ کے معنے شریعت کے نہیں ہو سکتے کیونکہ جتنی قومیں کفر سے تعلق رکھنے والی ہیں ان کی کوئی ایک شریعت نہیں.یہودی کتنے خرابی میں مبتلا ہیں کس قدر گمراہی ان میں پائی جاتی ہے مگر وہ ایک خدا کے قائل ہیں اس کے مقابلہ میں عیسائی بھی کافر ہیں مگر وہ توحید کے مسئلہ کے متعلق جو تمام مسائل میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے ان سے اختلاف رکھتے ہیں اور حضرت مسیحؑ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور خدا نے حضرت مریم ؑکو اپنے بیٹے کی پیدائش کے لئے بطور آلہ کے استعمال کیا.پھر عیسائیوں کے بعض فرقے ایسے ہیں جو حضرت مریم کو ایک رنگ میں خدا تعالیٰ کی بیوی تسلیم کرتے اور ان کی پرستش کرتے ہیں.چنانچہ کئی آرتھوڈکس فرقے حضرت مریم کو اسی حیثیت سے دیکھتے ہیں.اب دیکھو کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں ہی جو ایک کڑی کے دو سلسلے ہیں کس قدر اختلاف پایا جاتا ہے.پھر زرتشتی ہیں ان کی شریعت بالکل الگ ہے.یہود کے نزدیک خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی علامت اس دنیا کے انعامات ہیں لیکن زرتشتی اصل انعام کا وقت مرنے کے بعد کے زمانہ کو سمجھتے ہیں.چنانچہ بائبل اور انجیل کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو ان میں جزا و سزاکودنیا سے مخصوص قرار دیا گیا ہے یا کم سے کم دنیوی جزا و سزا پر بہت زور دیا گیا ہے.مگرزرتشتی تعلیم کو دیکھو تو وہ اگلے جہان سے تمام انعامات کو وابستہ قرار دیتی ہے.ژند اور اوستا میں سارا زور مرنے کے بعد کی زندگی پر ہے اور بار بار بتایا گیا ہے کہ وہاں گناہ گاروں کے لئے دوزخ اور نیک لوگوں کے لئے جنت ہو گی.گویا زرتشتی تعلیم کو پڑھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم اور ژند و اوستا کی تعلیم اس بارہ میں ایک ہی ہےجہاں تفصیلات شریعت میں قرآن کریم کے ساتھ یہودی تعلیمیں ملتی ہیں وہاں بعث بعد الموت کے معاملہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نظر نہیں آتا.بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور ژند و اوستا دونوں ایک منبع سے نکلی ہیں.پھر ہندو تعلیم لے لو تو اس کا کوئی جو ڑ یہودی تعلیم یا زرتشتی تعلیم کے ساتھ نہیں.ان کی ساری بنیاد اس بات پر ہے کہ نسلی طور پر بعض قوموں کو بعض قوموں پر فوقیت حاصل ہو تی ہے اورخدا اپنا سارا انعام ان کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے.اس میں شبہ نہیں کہ یہودی قوم میں بھی نسلی تفوّق کا اظہار کیا گیا ہے مگر دوسری قوموں کے خلاف اس میں وہ رنگ نہیں جو ہندو تعلیم میں پایا جاتا
Page 520
ہے.یہ نہیں کہ وہ ان کو غلام بنا کر رکھیں اور ان سے اچھوتوں کا سا سلوک کریں.مگر ہندو قوم میں ساری بنیاد نسلی تفوّق پر ہے.پھر تناسخ کو لے لو تو یہودیوں میں تناسخ کا کوئی ذکر ہی نہیں عیسائیوں میں بھی تناسخ کا کوئی ذکر نہیں ژند اور اوستا میں بھی تناسخ کا کوئی ذکر نہیں.پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اَلْکُفْرُ مِلَّۃٌ وَاحِدَۃٌ کہ کفرایک ملت ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی عبادت ایک ہے یا ان کے عقیدے ایک ہیں یا ان کی کتاب ایک ہے.کیونکہ ہمیں صریح طور پر نظر آتا ہے کہ ان کی عبادتیں الگ الگ ہیں ان کے عقیدے الگ الگ ہیں ان کی کتابیں الگ الگ ہیں پس مِلَّۃ کے معنے اس حدیث میں شریعت کے ہو ہی نہیں سکتےبلکہ اس حدیث میں مِلَّۃ کے معنے جتھے اور جماعت کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ۱سلام کے سوا جس قدر مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے مقابلہ میں جتھہ بن جاتے ہیں اس لئے ہمیشہ ان سے ہوشیار رہنا اور یہ نہ سمجھنا کہ فلاں ہندو ہے اور فلاں عیسائی، فلاں یہودی ہے اور فلاں پارسی.جب اسلام کا مقابلہ ہو گا یہ سارے کے سارے متحد ہوجائیں گے.چنانچہ گذشتہ تیرہ۱۳ سو سال کی تاریخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی صداقت کا ایک بیّن ثبوت ہے.مسلمان حکمرانوں نے اپنے عہد حکومت میں یہودیو ں سے اس قدر حسن سلوک کیا کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے.بڑے بڑے عہدوں پر ان کو فائز کیا مگر انہوں نے آخر مسلمانوں کے خلاف ہی تلوار چلائی.ہندوؤں کے ساتھ مغل بادشاہوں نے کیا کیا حسن سلوک کیا مگر ہندو آخر مسلمانوں کےہی دشمن ہوئے.سکھوں کو دیکھ لو ان کی موجودہ ریاستوں میں سے اکثر مسلمانوں کی ہی دی ہوئی ہیں.سکھوں کی حکومت احمد شاہ ابدالی نے بنائی.ان کے گوردواروں کی جائدادیں اکثر مسلمانوں کی دی ہوئی ہیں.لیکن وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کےساتھ مل جاتے ہیں.یہی حال پارسیوں کا ہے پس اَلْکُفْرُ مِلَّۃٌ وَاحِدَۃٌ کا یہ مفہوم نہیں کہ ان کی شریعت ایک ہے بلکہ اس میں ان کی قومی شیرازہ بندی اور جتھہ بندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ وہ اسلام کے خلاف ہمیشہ متحد ہوتے رہیں گے.غرض مِلَّــۃٌ میں دین کے علاوہ قومی شیرازہ بندی بھی شامل ہے اور میں نے بتایا ہے کہ خدمت اور احسا س قومی اس کا ایک حصہ ہے.پس جب ہم مِلَّۃٌ کےمعنے کریں تو اس میں شریعت کی طرف اشارہ نہیں ہو گا بلکہ قومی جتھہ بندی کی طرف اشارہ ہو گا اور اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ کے ساتویں معنے یہ ہو ں گے کہ قومی تعصب اور قومی جتھہ بندی کا کون منکر ہے جو شخص اس کا منکر ہو گا وہ ہمیشہ خرابی کی طرف جائے گا.یہ ایک عجیب بات ہے کہ بعض دفعہ بہتر سے بہتر لفظ بھی غلط معنوں میں استعمال ہو نے لگتا ہے.مجھے یاد ہے
Page 521
حضرت خلیفہ اوّل رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں تعصب بری چیز ہے، تعصب تو بڑی اچھی چیز ہے.اس وقت میری تعلیم چونکہ ابھی ابتدائی حالت میں تھی.اس لئے جب بھی آپ یہ فقرہ استعمال فرماتے مجھے یوں محسوس ہو تا کہ میرا جسم کانپ اٹھا ہے اور میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تعصب جیسی بری چیز کو آپ اچھا قرار دے رہے ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ یہ مضمون مجھ پر واضح ہو نا شروع ہوا اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ لفظ عربی ہے اور عربی میں اس کا اور مفہوم ہے اور اردو میں اور، عربی میں جہاںاس کے معنے برے ہیں وہاں اس کے معنے اچھے بھی ہیں.لفظ کی بناوٹ کے لحاظ سے اس کے معنے یہ ہیں کہ اپنے دین اور طریقے کے لئے غیرت کا ظاہر کرنا اور اس پر اگر حملہ ہو تو اسے دور کرنا.ظاہر ہے کہ یہ معنے اچھے ہیں.جس چیز کو انسان اچھا سمجھتا ہے اس کے لئے اظہار غیرت اور اس کی حفاظت کے لئے قربانی ایک بہترین فعل ہے.درحقیقت یہ لفظ اردو میں غلط استعمال ہو نے لگ گیا ہے.اور صرف برے معنوں میں محصور ہو کر رہ گیا ہے اور اسی وجہ سے ابتداءً مجھے حضرت خلیفۂ اوّل کے مذکورہ بالا فقرہ پر تعجب ہوا کرتا تھا.مگر آہستہ آہستہ جب میں نے زیادہ علم پڑھا تو پھر میری سمجھ میں یہ بات آنے لگ گئی کہ آپ کی بات ٹھیک ہے.ہم تعصّب کے معنے اردو میں صرف یہ لیتے ہیں کہ ناجائز طور پر قوم کی طرف داری کرنا.لیکن عربی میں اس کے دو مفہوم ہیں جن میں سے ایک کو اردو میں بالکل نظر انداز کر دیا جا تا ہے.میں نے بتایا تھا کہ اس آیت میں نیکی کی جڑوں کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ کون کون سی نیکیاں ہیں جن کے چھوڑنے سے بدیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کون کون سی نیکیاں ہیں جن کو اختیار کرنے سے مزید نیکیوں پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے.پس مِلَّۃٌ کےاقرار سے اس آیت میں ( میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ دین کا انکار فطرت کے خلاف ہے.ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جو فطرت کو بھول جائے.پس اس آیت میں دین کی ضرورت پر زور ہے ) اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کی فطرت صحیحہ اسے قومی خدمت کی طرف راغب کرتی ہے اور جو شخص قومی خدمت کی ضرورت کو محسوس کرے گا وہ لازماً انفرادی ضرورتوں کو مقدم کرنے والے شخص سے بہت زیادہ نیک کام کرے گا.بے شک انفرادی حقوق بھی ہوتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا بھی آجاتا ہے جب ان پر زور دینا گناہ کا موجب ہوتا ہے.مثلاً بدلہ لینا ہے.عیسائیت کہتی ہے بدلہ نہ لے.مگر مسیحی جب یہ تعلیم پیش کرتے ہیں تو وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کیونکہ مسیحیوں سے زیادہ بدلہ آج تک دنیا میں کسی قوم نے نہیں لیا.مگر اسلام کہتا ہے کہ موقع ہو تو بدلہ لے، نہ ہو تو نہ لے.اگر تمہیں اس با ت میں دنیا یا ظالم کا فائدہ نظر آتا ہے کہ بدلہ لو تو بدلہ لو ورنہ
Page 522
بدلہ نہ لو.اصل مقصد تو نیکی کا پھیلانا ہے اگر بدلہ لینے سے نیکی پھیلتی ہو تو بدلہ لو.اگر بدلہ نہ لینے سے نیکی پھیلتی ہو تو بدلہ نہ لو.یہ ہے اسلام کی تعلیم.عربوں میں تعصب بہت تھا.یعنی قومی خدمت اور قوم کے لئے قربانی کا احساس ان میں بہت زیادہ تھا.لیکن بعض دفعہ غلط طریق پر چل کر وہ اسے انتہا تک لے جاتے تھے اور یہ فعل نیکی نہیں بلکہ بدی بن جاتا تھا.چنانچہ بعض دفعہ غریب یا مسکین کی حمایت کے نام سے انہوں نے جنگیں کی ہیں جو سو سو سال تک بھی چلی گئی ہیں.مثلاً ایک عرب کے کھیت میں ایک کتیانے بچے دے دیئے.کسی عرب کا اونٹ کھل کا اس کھیت میں چلاگیا اور اس کے پاؤں تلے ایک بچہ کتیا کا مر گیا.کھیت والے نے سمجھا کہ کتیا نے میرے کھیت میں پناہ لی تھی اس کا بچہ مارا گیا ہے اس لئے مجھے بدلہ لینا چاہیے اس نے اس اونٹ کو مار دیا جس کا اونٹ تھا وہ ایک اور عرب کا مہمان تھا اس عرب نے کہا کہ چونکہ میرے مہمان کا اونٹ مارا گیا ہے اس لئے اس کا بدلہ لینا میرا فرض ہے اس لئے اس اونٹ مارنے والے عرب کو مار دیا.اس مقتول کی قوم نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لئے اجتماع کیا جس پر قاتل کی قوم نے اپنے بھائی کی مدد کا فیصلہ کیا اور باہم جنگ شروع ہو گئی جس میں آہستہ آہستہ دوسری اقوام بھی شامل ہوتی گئیں اور سارے عرب میں سو سال تک جنگ ہو تی رہی( الکامل فی التاریخ ذکر مقتل کلیب و الایام بین بکر و تغلب).جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے عرب پر حکومت عطا فرمائی تو اس وقت تک ہزاروں انسانوں کا خون اسی قسم کے لغو بدلوں میں لیا جا چکا تھا اور سینکڑوں انسان ایسے تھے جن کے خون کا بدلہ ابھی لیا جانے والا تھا.اس لئے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لئے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وعظ فرمایا جس میں اور باتوں کے علاوہ آپ نے ایک یہ بات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو عرب میں بعض قبائل کے بعض قبائل پر خون کے حق قائم ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے آدمی مار ڈالے تھے.مگر کبھی نہ کبھی یہ چیز ختم ہونی چاہیے ورنہ عرب کی طاقت بالکل ٹوٹ جائے گی اس لئے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ ہر خون کا بدلہ لینے کی حکومت ذمہ وار ہو گی افراد کو یہ حق حاصل نہیں ہو گا کہ وہ خود بخود کسی قتل کا بدلہ لیں.باقی رہے پچھلے خون سو آج میں ان سارے خونوں کو معاف کرتا ہوں اب کسی کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں سے کسی خون کا بدلہ لے اس پر سب لوگ تسلی پا گئے اور امن قائم ہو گیا.ورنہ اگر وہ خون باقی رہتے تو اسلامی زمانہ میں بھی خونریزی کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو جاتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومی خدمت کے غلط جذبہ کو ایک نیک رو سے بدل دیا اور بتایا کہ یہ قومی خدمت نہیں قوم کی تباہی کی صورت ہے اور اس طرح قومی خدمت کا صحیح جذبہ پیدا کر کے عرب کو ایک بلاءِ عظیم سے نجات دلوادی.میں نے اس سے پہلے دین کے معنوں میں ضبط کا ذکر کیا تھا.ضبط اور چیز ہے اور خدمتِ ملی کا احساس اور چیز
Page 523
ہے.ضبط و نظام ظاہر پر دلالت کرتا ہے تم بائیں طرف چلتے ہو تو اس لئے نہیں کہ تمہارا دل بائیں طرف چلنے کو چاہتا ہے بالکل ممکن ہے تمہارا دل دائیں طرف چلنے کو چا ہے مگر تم کہتے ہو میں قوم کا حکم مانتے ہوئےبائیں طرف چلوں گا.لیکن قومی خدمت کے یہ معنے ہو تے ہیں کہ اگر فرد یہ دیکھے کہ قوم اس کی ہلاکت اور بربادی سے بچ سکتی ہے تو وہ بلا دریغ اپنے آپ کو قربان کر دے.ضبط و نظم میں حکم کی اطاعت کا سوال ہو تا ہے لیکن ملکی یا قومی جذبہ میں حکم کوئی نہیں ہوتا.تم خود قوم کا فکر رکھتے ہو، تم خودملک کی ترقی کا احساس رکھتے ہو اور جب تمہیں قومی یا ملکی بر تری کا احساس مجبور کرتا ہے تم اپنے آپ کو ملک اور قوم کے لئے قربان کر دیتے ہو.گذشتہ جنگ عظیم میں جاپانی فوج کے راستہ میں ایک جگہ بجلی کی تاروں کی باڑ لگا دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی فوج آگے نہیں بڑھ سکتی تھی.انہوں نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح ا س کو دور کریں مگر ناکام رہے.آخر جاپان کے کچھ نو جوان اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے وہ اپنے پیٹوں سے بم باندھ کر اس تار پر گر گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو تباہ ہو گئے مگر بجلی کی تار بھی ٹکڑے ہو گئی اور فوج کے لئے راستہ بن گیا.انہیں حکم نہیں تھا کہ تم ایسا کرو مگر چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اگر حالت اسی طرح رہی تو ہماری فوج وقت پر آگے نہیں بڑھ سکے گی.اس لئے وہ ان کو بچا نے کے لئے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے.میں اس جگہ اس سوال پر بحث نہیں کر رہا کہ یہ طریق قربانی کا اسلام کے مطابق ہے یا نہیں.میں یہ بتا رہا ہوں کہ قومی خدمت کے لئے قربانی اور ضبط و نظم کے لئے قربا نی الگ الگ اقسام کی ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عیسائیوں سے لڑائی شروع ہوئی تو شام میں ایک موقع پر دشمن کا ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہو گیا.مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی.عیسائیوں نے پہلےمخفی طور پر یہ پتہ کرا لیا کہ مسلمانوں میں صحابی کون کون سے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے کچھ تیر انداز ایک ٹیلے پر بٹھا دیئے اور انہیں ہدایت کردی کہ وہ اپنے تیروں کا خصوصیت سے صحابہؓکو نشانہ بنائیں.وہ جانتے تھے کہ جب جب بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو باقی فوج کے دل خود بخود ٹوٹ جائیں گے اور وہ میدان سے بھاگ جائے گی.نتیجہ یہ ہوا کہ کئی صحابہؓ مارے گئے اور کئی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں.اس پر مسلمانوں کو سخت فکر پیدا ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ اگر اب ہم آگے بڑھے تو تمام کے تمام صحابہؓ ختم ہو جائیں گے.چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چا ہئے.اس پر بعض نوجوانوں نے اپنی خدمات پیش کیں اور کہا کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر نے کے لئے تیار ہیں اور ان خدمات کے پیش کرنے میں سب سے مقدم وہ نوجوان تھا جس کے خاندان نے اسلام کی دشمنی کا بیج مکہ میں بو یا تھا یعنی ابو جہل کا بیٹا عکرمہ.ان نو جوانوں نے کہا کہ صحابہ ؓ بہت بڑی خدمات کر چکے ہیں اب ہم جو بعد میں آئے ہیں ہمیں
Page 524
ثوا ب حاصل کرنے کاموقع دیا جائے.ہم مل کر قلب لشکر پر حملہ کریں گے اور عیسائی جرنیلوں کو مار ڈالیں گے.حضرت ابو عبیدہ جو لشکر کے کمانڈر تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے.اس طرح تو جس قدر نوجوان جائیں گے سب کے سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے.انہوں نے کہا ٹھیک ہے مگر اس کے سوا اب چارہ بھی کوئی نہیں.کیا آپ یہ پسندکریں گے کہ ہم نو جوان تو بچ رہیں اور صحابہ ؓ مارے جائیں ؟ اس پر انہوں نے حضرت خالد ؓ سے مشورہ لیا انہوں نے بھی کہا کہ عکرمہ کی رائے ٹھیک ہے دشمن نے ہماری دکھتی رگ کو معلوم کر لیاہے اور اب وہ صحابہ کو ختم کر نا چاہتا ہے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ساٹھ نو جوان اپنے ساتھ لیں اور قلب لشکر پر حملہ کر دیں.آخر حضرت ابو عبیدہ نے ان کے اصرار پر اجازت دے دی اور ساٹھ نو جوانوں نے قلب لشکر پر حملہ کر کے اسے شکست دے دی لیکن اس لڑائی میں ان میں سے اکثر نوجوان مارے گئے.ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ جب عیسائی لشکر کو شکست ہو گئی اور وہ سب بھاگ گئے تو میں زخمیوںکی دیکھ بھال کے لئے میدان جنگ میں گیا.میں نے دیکھا کہ عکرمہ ؓ بن ابی جہل ایک جگہ ز خمی تڑپ رہے تھے میں نے دیکھا اور سمجھا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہوئی ہے.پانی کی چھاگل میرے پاس تھی میں آگےبڑھا تاکہ چھاگل ان کے منہ سے لگاؤں مگر ابھی میں نے یہ ارادہ ہی کیاتھا کہ عکرمہ ؓ نے فضل بن عباسؓکی طرف اشارہ کیا جو ان کے پہلو میں پڑے زخموں سے تڑپ رہے تھے اور کہاکہ انہیں مجھ سے زیادہ پیاس معلوم ہوتی ہے تم جاؤ اور پہلے فضل کو پانی پلاؤ وہ مجھ سے زیادہ حق دار ہیں.وہ کہتے ہیں میں پانی پلانےکے لئے فضل کی طرف گیا تو انہوں نے ایک اور شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو ان کے قریب ہی زخموں سے تڑپ رہا تھا کہا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ اسے مجھ سے بھی زیادہ پیاس معلوم ہو تی ہے وہ کہتے ہیں اس وقت دس زخمی مسلمان قریب قریب پڑے ہوئے تھے.میں ایک سے دوسرے کے پاس دوسرے سے تیسرے کے پاس اور تیسرے سے چوتھے کے پاس گیا مگر ہر شخص نے مجھے یہی کہا کہ دوسرے کو پانی پلاؤ وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے.جب میں آخری کے پاس پہنچا تو وہ مر چکا تھا.پھر واپس لوٹا تو نواں شخص بھی مر چکا تھا.پھر آٹھویں کی طرف بڑھا تو وہ بھی مر چکا تھا.اس طرح ایک ایک کر کے سب کو میں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں.پانی کی چھاگل میرے ہاتھ میں تھی.مرنے والے مرچکے تھے مگر مرتے وقت ان میں سے کسی ایک نے بھی پانی کا ایک گھونٹ نہ پیا محض اس لئے کہ میرا ساتھی مجھ سے زیادہ پیاسا معلوم ہو تا ہے.یہ ہے قومی روح یعنی اپنے نفس کو مقدم کر نے کی بجائے قومی ضرورتوں کو انسان مقدّم رکھے اور اپنے آپ کو قومی مفاد اور برتری کے لئے قربان کر دے مگر قومی ایثار کا صحیح جذبہ جب بھی پیدا ہو گا قومی خدمت سے پیدا ہو گا.جب قومی خدمت کا صحیح جذبہ کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ بے انتہا قربانیاں
Page 525
کرنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے.جس شخص کے اندر قومی جذبہ پیدا ہو گا اس کا مطمحِ نظر وسیع ہو جائے گا.ایک کمزور سے کمزور اور جاہل سے جاہل انسان کو بھی جاکر دیکھو اس کی قوت فکر اتنی مری ہوئی نہیں ہو تی جتنی لوگ سمجھتے ہیں.جاہل سے جاہل ماںبھی بچے کا کتنا فکر کر تی ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورتوں کا وہ خیال رکھتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو.گاؤں میں غریب سے غریب گھروں میں چلے جاؤ جب شادی بیاہ کا موقع آئے گا عورت اپنے پٹارے میں سے کوئی کپڑ انکالے گی اور لڑکی کے جہیز میں رکھ دے گی اور جب اس سے پوچھو کہ یہ کپڑا تم نے کب خریدا تھا تو وہ کہے گی دس سال ہوئے میں نے یہ کپڑا خریدا تھا پھر اس لئے رکھ دیا کہ بچی کی شادی کے وقت کام آئے گا.اگر اس میں عقل نہیں تھی تو اس نے اتنی لمبی باتیں کس طرح سوچ لیں.پھر بیسیوں دفعہ خاوند کے پاس معاملہ ادا کرنے کے لئے روپیہ نہیں ہو تا تو عورت اپنی پوٹلی میں سے روپیہ نکال کر اسے دے دیتی ہے اور جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ روپیہ تم نے کہاں سے لیا تو وہ بتاتی ہے کہ پیسہ پیسہ کرکے میں جمع کرتی چلی گئی تھی تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے.وہ ایسا کیوں کرتی ہے اسی لئے کہ اس کے اندر عائلی جذبہ ہو تا ہے جو اسے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور جب وہ سوچتی ہے تو اسے مشکلات نظر آتی ہیں پھر وہ ان مشکلات کے علاج پر غور کرتی ہے اور آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے.اسی طرح ہر شخص اپنے بچے کے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہو تا ہے میں اسے کس طرح تعلیم دلاؤں گا کس طرح اس کے کپڑوں اور کھانے کا انتظام کروںگا اس بارہ میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکے گا.اگر اسی قوت فکر کو قومی بنا دو تو ہر انسان قومی ضروریات کے متعلق سوچ رہاہوگا اور وہی جاہل انسان جس کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ وہ کسی کام کا نہیں جب اسے ان باتوں کے سوچنے پر لگا دو گے تو اس کی نظر وسیع ہو جائے گی.در حقیقت ہم جس شخص کو جاہل کہتے ہیں قومی نقطہ نگاہ سے اس کے صرف اتنے معنے ہو تے ہیں کہ اس کے دماغ کو سوچنے کی طرف توجہ نہیں.یہ معنے نہیں ہوتے کہ وہ سوچ نہیں سکتا.میں نے احمدیہ جماعت کی مجلس شوریٰ میں دیکھا ہے اور میرا بیس پچیس سال کی مجالس شوریٰ کا یہ تجربہ ہے کہ بسا اوقات کسی فیصلہ کی پوری زنجیر اس وقت تک مکمل نہیں ہو تی جب تک ایک عام آدمی کی رائے بھی اس کے ساتھ نہ ملا لی جائے سو میں سے صرف ایک دفعہ مجھے اپنے طور پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے.ورنہ ننانوے دفعہ میں فیصلہ اسی طرح کرتا ہوں کہ کچھ اس کی رائے میں سے لیا اور کچھ اس کی رائے میں سے، اور ایک نتیجہ پیدا کرلیا.اگر ہم عوام کو مجلس مشاورت میں شامل نہ کرتے تو وہ بھی صرف اپنے گھر کی ضروریات کے متعلق ہی اپنے دماغوں سے کام لینے کے عادی ہوتے.لیکن جب ہم نے ان کو اپنی مشاور ت میں شامل کر لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے دماغ ترقی کر گئےچنانچہ ان کی آرا ء کے ٹکڑے ٹکڑے
Page 526
مل کر ایک مکمل سکیم بن جاتی ہےجو جماعت کے لئے نہایت مفید اور بابرکت ثابت ہو تی ہے.غرض جس طرح فرد اپنی ضرورتوں کے متعلق سوچ کر سکیم بنا لیتا ہے اسی طرح اگر اس کا دماغ قومی ضرورتوں کی طرف منتقل کر دیا جائے تو ہر فرد قومی ضرورتوں کے متعلق سوچنے لگ جائے اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ہر شخص اس کی قابلیت رکھتا ہے.جنگل میں رہنے والاہو یا پہاڑ پر رہنے والا، گاؤں میں رہنے والا ہو یا شہر میں رہنے والا.ہر شخص پاکستان کے مستقبل کے متعلق بھی سوچ سکتا ہے.فلسطین کے مستقبل کے متعلق بھی سوچ سکتا ہے.اسی طرح دنیا کے ہر سیاسی مسئلہ کے متعلق سوچ سکتا ہے.نقص یہ ہے کہ اسے یہ احساس نہیں کرایا گیا کہ تم پر قوم کے متعلق ذمہ واری ہے اس لئے وہ یہ تو کرتا ہے کہ کبھی اپنی بیوی کے متعلق سوچتا ہے کبھی اپنی لڑکی کے متعلق سوچتا ہے.کبھی اپنے لڑکوں کے متعلق سوچتا ہے، کبھی اپنے رشتہ داروں کے متعلق سوچتا ہے مگر وہ اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے مذہب کے متعلق کبھی نہیں سوچتا.اس لئے نہیں کہ وہ سوچ نہیں سکتا.بلکہ اس لئے کہ وہ اس کا عادی نہیں.اگر قومی جذبہ پیدا ہو جائے تو ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی کچھ نہ کچھ سکیمیں سوچنے لگ جائے گا اور اگر قومی جذبہ پیدا نہیں ہو گا تو عام لوگ تو الگ رہے پڑھے لکھے بھی اپنی قوم سے غافل رہیں گے.نہ انہیں اپنی قوم کے نقائص کا پتہ ہو گا نہ اس کے علاج کا فکر ہو گا اور سارا نظام ڈھیلا ہو جائے گا.اصل بات یہ ہے کہ اس نکتہ کو سمجھا نہیں گیا کہ جس طرح فرد کا دماغ ہے اسی طرح قوم کا بھی دماغ ہے.قوم کا دماغ ایک غیر مادی او ر روحانی چیز ہے مگر اس سے زیادہ یقینی اور پختہ چیز اور کوئی نہیں جب کسی قوم کے افراد میں جذبہ ملت پیدا ہو جاتا ہے تو تمام افراد قومی ضرورتوں کے متعلق سوچنے لگ جاتے ہیں اورقومی ضرورتوں کے متعلق سوچنے اور غور و فکر کرنے کے نتیجہ میں قومی روح پیدا ہو جاتی ہے اور قومی روح سے قومی دماغ پیدا ہو تا ہے جو نظر تو نہیں آتا مگر وہ ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.جس قوم میں قومی دماغ پیدا ہو جاتا ہے وہ باوجود افراد کے علم کی کمی کے جیت جاتی ہےاور جس قوم میں قومی دماغ پیدا نہیںہو تا وہ باو جود افراد کی علمیت کے ہار جاتی ہے.جس طرح فرد حکومت کا قائم مقام نہیں ہو سکتا اسی طرح فردی دماغ قومی دماغ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا.گذشتہ دنوں میں ملک میں جو فساد ہوا اس میں انفرادی طور پر کچھ مسلمانوں نے بھی اپنے بچاؤ کی تدبیریں کی تھیں مگر قومی طور پر انہوں نے کوئی تدبیر نہیں کی تھی.بعض شہروں نے بے شک بعض تدابیر اختیار کی تھیں جیسے امرتسر ہے مگر شہر بھی ایک ملک کے مقابلہ میں فرد کی حیثیت رکھتے ہیں.نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ایسی بری طرح پٹے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے.سکھ مشرقی پنجاب میں بائیس۲۲ فیصدی تھے اور مسلمان چوالیس۴۴ فیصدی مگر
Page 527
بائیس۲۲ فیصدی نے چوالیس ۴۴ فیصدی کو مارا اور ایسی بری طرح مارا کہ انہیں ایک قدم بھی نکلنے نہیں دیا.اسی وجہ سے کہ سکھوں میں قومی دماغ تھا مگر مسلمانوں میں صرف انفرادی دماغ تھا قومی دماغ نہیں تھا.جب تک قومی دماغ نہ ہو اس وقت تک بڑے بڑے مصائب کا مقابلہ کبھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ کوئی بڑی ترقی کی جا سکتی ہے.جس طرح انسانی جسم میں ہزاروں ہزار پیچیدہ کام کرنے والےاعضاء پائے جاتے ہیں.دانت چباتے ہیں گلے کی نالیوں کے ذریعہ غذا معدہ میں پہنچتی ہے معدہ ا س کو ہضم کرتا ہے اور پھر اعلیٰ درجے کا خون دل و دماغ اور دوسرے اعضا ء میں جاتا اور انسانی زندگی کو بر قرار رکھتا ہے.اسی طرح ان سے بھی زیادہ ایک اور اہم چیزجسم انسانی میں پائی جاتی ہے اور وہ روح ہے جس پر تمام حیات کا دارو مدار ہے اور جس کے متعلق سائنسدان بھی ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکے کہ وہ کیا چیز ہے.بہرحال وہ ایک خلاصہ ہے ہزاروں ہزار پیچیدہ تغیرات کا.بے شک وہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی.بے شک دنیا یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ جسم انسانی کے کون سے عضو میں پوشیدہ ہے مگر اس سےانکار نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی چیز ایسی ضرور ہے جس کی عدم موجودگی انسانی جسم کو بالکل بے کار بنا دیتی ہے.جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کی سب چیزیں موجود ہو تی ہیں کہیں غائب نہیں ہو جاتیں.دل بھی ہو تا ہے، دماغ بھی ہوتا ہے، معدہ اور جگر اور انتڑیاں بھی ہو تی ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی ہو تے ہیں مگر دل اور اعصاب کا تمام نظام یک دم بے کار ہو جاتا ہے.اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی اور چیز انسانی جسم میں ضرور ہے.وہ انگلی میں ہے یا بازو میں، دل میں ہے یا دماغ میں، ہمیں اس کا علم نہیں مگر اس کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا.جس طرح انسانی جسم میں روح موجودہو تی ہے اور اسی پر تمام حیات کا دارو مدار ہو تا ہے اسی طرح ایک قومی روح بھی ہو تی ہے اور ایک قومی دماغ بھی ہو تا ہے.جب تک کسی قوم میں قومی دماغ قائم رہتا ہے وہ تمام اقوام پر غالب رہتی ہے اور کوئی قوم ا س کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتی.انگریزوں کو لے لو ان میں قومی دماغ ہےجس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسری اقوام پر غالب رہتے ہیں.جرمن طنزاً کہاکرتے ہیں کہ انگریز بڑا جاہل ہے وہ اچھے عالم پیدا نہیں کر سکتا.فرانسیسی طنزاً کہا کرتا ہے کہ انگریز صرف نقّال ہے وہ موجد پیدا نہیں کر سکتا.چنانچہ جہاں تک انفرادی ایجادات کا تعلق ہے انگریز جرمنوں کا ہر گز مقابلہ نہیں کر سکتے فلسفہ کا سوال آئے تو یقیناً انگریز جرمن کا خوشہ چین ہے.ادب اور اخلاق کا سوال آئے تو یقیناً انگریز فرانس کا مقابلہ نہیں کر سکتا.آرٹ میں بھی فرانس اور اٹلی کا مقابلہ انگریزوں کے بس کی بات نہیں.مگر باجود اس کے کہ جرمن اور اٹلی اور فرانس والوں کا انفرادی دماغ بہت اعلیٰ ہے پھر بھی قومی لحاظ سے انگریز ہمیشہ غالب رہتے ہیں اس لئے کہ گو انگریزوں کا انفرادی دماغ اتنا اعلیٰ نہیں مگر قومی دماغ ان میں پایا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں.ابتدا زمانہ اسلام میں مسلمانوں کو جو
Page 528
غلبہ حاصل ہوا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان میں قومی دماغ پایا جاتا تھا.ورنہ مسلمانوں کی تعلیم رومیوں سے زیادہ نہیں تھی.رومی سالوں تک مسلمانوں کو پڑھا سکتے تھے.اسی طرح جہاں تک تجارتی تمدن کا تعلق ہے مسلمان ایرانیوں سے بہت پیچھے تھے یہی حال دوسرے امور کا ہے.مذہب کو چھوڑ کر کوئی ایک فردی خوبی بھی ایسی نہیں تھی جس میں مسلمان رومیوں اور ایرانیوں کا مقابلہ کر سکیں مگر پھر بھی یہ حالت تھی کہ مسلمان جہاں جاتا رومی بھی بھاگ جاتا اور ایرانی بھی بھاگ جاتا.آخر وہ کیا چیز تھی جو مسلمانوں کو حاصل تھی.وہ چیز یہی تھی کہ اسلام کے ذریعہ سے مسلمانوں میں قومی دماغ پیدا ہو چکا تھا اور قومی دماغ کا فردی دماغ مقابلہ نہیں کر سکتا.قومی دماغ کا یہ مفہوم ہو تاہے کہ قوم کے ہر فرد میں یہ احساس ہو تا ہے کہ میں کچھ چیز نہیں اصل چیز قوم ہے.چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صحابہ ؓ نے جو کچھ قربانیاں کیں وہ اس بات کا ایک بیّن ثبوت ہیں کہ کس طرح وہ ہر چیز میں قوم کے مفاد کو مدّ ِنظر رکھتے تھے.دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرد نہیں تھی بلکہ وہ ایک نشان تھی قومی عظمت کا.اس لئے آپ کے لئے جو قربانیاں کی گئیں وہ فرد کے لئے نہیں تھیں بلکہ قوم کے لئے ہی تھیں.ان کی قربانیوں کا اندازہ اسی واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک جنگ میں دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی کہ حضرت طلحہؓ نے اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے کر دیا تاکہ کوئی تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آلگے اور انہوں نے اپنا ہاتھ برابر اسی طرح رکھا یہاں تک کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا اور ساری عمر کے لئے بے کار ہوگیا(البخاری کتاب المغازی اذھمت طائفتین ان تفشلا).کیا جذبہ ایمان تھا کہ انہوں نے اُف تک نہ کی اور اپنے ہاتھ کو برابر تیروں کی بوچھاڑ میں کھڑے رکھا.ایک دفعہ حضرت طلحہ ؓ سے کسی نے پو چھا کہ طلحہ جب تمہارے ہاتھ پر تیر لگتے تھے تو کیا تمہارے منہ سے اُف بھی نہیں نکلتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا اُف تو نکلنا چا ہتی تھی مگر میں نکلنے نہیں دیتا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرا ہاتھ ہل نہ جائے اور کوئی تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آلگے.یہ واقعہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں کوئی فرد باقی نہیں رہا.ہمارا صرف یہی کام ہے کہ ہم قوم کے لئے یا قوم کے نشان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رات اور دن قربانیاں کریںاور اپنے آپ کو اسی راہ میں قربان کر دیں.اُحد کی جنگ جب ختم ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زخمیوں کی دیکھ بھال کےلئے روانہ کیا انہوں نے ایک انصاری صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت نازک حالت میں ہیں.وہ اس کے قریب گئے اور اس سے کہا کہ بھائی کوئی تمہارا پیغام ہو تو مجھے بتا دو میں تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں تک پہنچا دوں گا.اس نے کہا کہ میں اسی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی مدینے والا ملے اورمیں اس کے ذریعہ اپنے رشتہ داروں کو ایک پیغام بھجواؤں.
Page 529
اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے لاؤ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو اور وعدہ کرو کہ میرا پیغام میرے خاندان تک پہنچادوگے.انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر اقرار کیا کہ میں تمہارا پیغام ضرور پہنچا دوں گا.اس پر ان زخمی صحابی نے کہا میرے عزیزوں اور رشتہ داروں اور بھائی بندوں کو جا کر کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کا بہترین خزانہ ہیں اور یہ ایک قومی امانت ہیں جو ہمارے پاس ہے مجھے یقین ہے کہ تمہارے دل میں بھی اس قیمتی متاع کی صحیح قدرو قیمت کا احساس ہو گا.تاہم میں بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام تمہیں پہنچا دوں کہ جب تک ہم زندہ رہے ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں ہو نے دی اور اس کی حفاظت میں اپنا پورا زور صرف کر دیا.اب ہم مرنے لگے ہیں اور اپنے پیچھے اس امانت کو چھوڑے جا رہے ہیں میں اپنے تمام بیٹوں، بھائیوںاور ان کی اولاد سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس مقدس امانت کی حفاظت کریں گے اور ا س میں کسی قسم کی کو تاہی واقعہ نہیں ہونے دیں گے.(السیرۃ الـحلبیۃ غزوۃ احد) مرنے والا مرتا ہے تو کس طرح کبھی اسے اپنی بیوی کا خیال آتا ہے کبھی اپنے بچوں کا خیال آتا ہے وہ اگر کچھ بتاتا بھی ہے تو یہ کہ فلاں سے میں نے اتنا روپیہ لینا ہے.فلاں کو اتنا قرض دینا ہے.بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے.بیوی کے گذارے کا یہ انتظام کیا جائے.مگر وہ صحابی مرتے وقت بھی اگر خیال کرتا ہے تو اپنی قوم کا بلکہ نوع انسانی کا.وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اپنی قوم ہی کی نہیں بلکہ نوع بشر کی روح کو سمٹا ہوا پاتا ہے اور اس کی قومی روح انفرادی حقوق کو بھول جاتی ہے، وہ صرف قوم اور اس کے مظہر کو دیکھتا ہے اور مرتے ہوئے اپنے باقی ماندہ خاندان کو زندہ رہنے کی نہیں بلکہ مرنے کی تلقین کرتا ہے.اپنا حصہ لینے کی نہیں بلکہ اپنا حصہ قربان کرنے کی وصیت کرتا ہے.کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ فرد اور خاندان کی عزت اور بچاؤ، قوم کی عزت اور بچاؤ کے ساتھ وابستہ ہے.یہ روح اگر اب بھی مسلمانوںمیں پیدا ہوجائے تو ان کا مقابلہ نہ سکھ کر سکتے ہیں اور نہ ہندو کر سکتے ہیں.مسلمان یوں تو سکھوں پر ہمیشہ پھبتی اڑاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سکھ بڑی بے وقوف قوم ہے لیکن سکھ میں قومی دماغ ہےجس سے مسلمان ابھی تک محروم ہے اور یہی وجہ ہے کہ قلیل التعداد ہو نے کے با وجود مشرقی پنجاب میں سکھ جیت گیا اور مسلمان ہار گیا.غرض قومی دماغ بڑی قیمتی چیز ہو تی ہے اور جب کسی قوم میں یہ دماغ پیدا ہو جائے تو اس کی علامت یہ ہو تی ہے کہ ہر فرد قومی بہتری کے متعلق سوچتا اور غور وفکر کرتا ہے.جہاں بھی دو چار افراد مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں فلاں کمزوری ہے اوراس کا یہ علاج ہے فلاں نقص ہے اور اس کا یہ علاج ہے.پھر ایک محلہ کے لوگ دوسرے محلہ والوں سے ملتے ہیں تو وہاں بھی یہی ذکر کرتے ہیں.تیسرے محلہ والوں سے ملتے ہیں
Page 530
تو ان سے بھی یہی ذکر کرتے ہیں.پھر ایک شہر کے لوگ جب دوسرے شہر والوں سے ملتے ہیں تو وہ بھی یہی قومی تذکرہ کرتے ہیں.نتیجہ یہ ہو تا ہے کہ دماغوں میں ایک اشتراک پیدا ہو جاتا ہے.اور قوم کے اندر ایک ایسی روح پیدا ہوجاتی ہے کہ سب کی نظر صرف ایک ہی جہت کی طرف اٹھتی ہے.ہندوؤں میں یہی سپرٹ تھی جس نے انہیں کامیاب کیا.ادنیٰ سے ادنیٰ ہندو بھی اگر کوئی شکایت کرتا تو بڑے سے بڑا افسر بھی جب درخواست کے نیچے مثلاً دیوی چند کا نام لکھا ہوا دیکھتا تو وہ کہتا کہ جو کچھ دیوی چند کہہ رہا ہے ٹھیک ہے.اس کے مقابلہ میںاگر ایک مسلمان افسر بھی کوئی شکایت کرتا تو وہ سمجھتے کہ یہ غلط ہے مسلمان جھوٹ بول رہا ہے اور ہندو سچ بول رہا ہے.دوسری طرف مسلمان افسروں کی یہ حالت تھی کہ اگر ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ان کے پاس پہنچتا تو وہ بھی ہندو کی تائید کرتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان بڑا نصاف پسند ہے حالانکہ وہ جو کچھ کرتا انصاف اور اسلام کے بالکل خلاف ہو تا تھا.محض اس لئے کہ ہندو اس کی تعریف کریں وہ مسلمان کے خلاف چلتا اور پھر اس کانام انصاف رکھتا.یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ مسلمانوں کے اندر قومی روح نہیں تھی.چنانچہ جب گذشتہ مصیبت آئی وہ بری طرح شکست کھا کر بھاگے کیونکہ قومی مصیبت کے وقت فردی دماغ کام نہیں دیتا بلکہ قومی دماغ کام دیتا ہے اور قومی دماغ اسی وقت پیدا ہو تا ہے جب سب افراد کے دماغ ایک ہی جہت پر کام کر رہے ہوں.اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ مجھےبتاؤ تو سہی کہ وہ کون ہے جو قومی خدمت کے جذبہ سے منکر ہے ؟ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ ضرور تباہ ہو گا.اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مکہ والوں میں اور دوسرے غیر عربوں میں صحیح قومی خدمت کا جذبہ نہیں اس لئے ان کا اتحاد عارضی ثابت ہو گا.خود ان کی قوم سے غدار پیدا ہوتے رہیں گے لیکن مسلمانوں میں قومی خدمت کا جذبہ ہے اس لئے ان میں قومی دماغ پیدا ہے اور بوجہ قومی دماغ کے ان کا غریب اور امیر ایک سلک میں پرویا ہوا ہے.وہ سب کے سب ایک مقصد سامنے رکھتے ہیں جس کو ذاتی مقاصد پر قربان کر نے کے لئے وہ کسی قیمت پر بھی تیار نہیں اس لئے لازماً مسلمان جیتیں گے اور ان کے دشمن ہاریں گے.دین کے آٹھوین معنے وَرَ ع کے (۸)آٹھویں معنے دین کے وَرَع کے ہیں.وَرَع کےمعنے شبہات سے محفوظ رہنے کی کوشش کے ہیں یعنی وہ چیزیں جو نا پسندیدہ اور بُری ہیں ان سے احتراز کرے اور ان سے محفوظ رہنے کی خواہش رکھے.قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانی نفس کی تین حالتیں ہو تی ہیں ایک حالت نفس امّارہ کی ہوتی ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ کہہ کر اشارہ فرمایا ہے یعنی نفس کی
Page 531
وہ حالت جس میں وہ بدیوں کا حکم دیتا ہے اور انسان بدیوں کاایسا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ اور عیب کو پسند کرنے لگ جاتا ہے.اور ایک حالت نفس کی نفس مطمئنّہ ہو تی ہے یعنی وہ نفس اپنی حالت پر خوش ہو جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ میرا وجود خدا تعالیٰ کے خاص منشاء کے ماتحت بعض مخصوص اغراض اور مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے.او رجو سامان خدا تعالیٰ نے میرے لئے پیدا کئے ہیں وہ بہرحال میرے لئے مناسب حال ہیں گویا وہ اپنی حالت پر مطمئن ہوجاتا ہے.مجنون کی طرح یہ نہیںکرتا کہ کبھی خدا کی طرف چلا جائے اور کبھی شیطان کی طرف.کبھی دین کی طرف چلا جائے اور کبھی دنیا کی طرف.بلکہ نفس مطمئنّہ وہ ہے جو خدا کے پاس گیا اور اس کے پاس ٹک گیا.پھر وہاں سے ہلا نہیں.تیسرا نفس نفسِ لوّامہ ہو تا ہے جو بدیوں کو دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ یہ بدیاں ہیں اور نفس کو ملامت کرتا ہے کہ تمہیں ان بدیو ں سے بچنا چاہیے.کسی سے بدی سرزد ہو جائے تو وہ افسوس کرتا ہے اور استغفار میں لگ جاتا ہے اور اپنے نفس کو سخت ملامت کرتا ہے جس پر لفظ لوّامہ دلالت کرتا ہے.یہ حالت وَرَع کی ادنیٰ حالت ہے ورنہ اصل وَرَع یہ ہے کہ نفس کو یہ روکتا ہے اور وہ اس کے روکنے سے گناہ سے باز آجاتا ہے.اسی نفس لوّامہ کو انگریزی دان لوگ کانشنس کہہ دیتے ہیں یا پرانے طریق کے لوگ ضمیر کی آواز کہہ دیتے ہیں.عربی زبان میں ضمیر کے معنے انسان کے اندرونہ کے ہیں.ضمیر کی آواز کے معنے ہوتے ہیں انسان کی اندرونی طاقتوں کا مطالبہ.اب یورپ نے اس کانشنس کا بھی انکار کر دیا ہے.پہلے وہ لوگ بڑی کثرت سے کانشنس کانشنس کہا کرتے تھے مگر اب وہاں ایسے فلاسفر پید اہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل لغو بات ہے نفس لوّامہ یا کانشنس یا ضمیر کوئی چیز نہیں درحقیقت رسم و رواج اور انسانی عادات کا ایک ردِّ عمل ہو تا ہے اسے لوگ ضمیرکی آواز کہہ دیتے ہیں.جس ماحول میں انسان رہتا ہے اور جس قسم کی رسوم و عادات کا وہ شکار ہو تا ہے اس کے خلاف جب کوئی بات اس کے کان میں پڑتی ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو تی ہے مثلاً گائے ہے ہندو گائے نہیں کھاتا.لیکن مسلمان کھاتا ہے اور اسے ذرا بھی برا محسوس نہیں ہوتا انگریز گائے کھاتا ہے اور اسے کچھ بھی بُرا محسوس نہیں ہوتا.اگر ہندو کے سامنے گائے کے گوشت کا نام لے دو تو اسے فوراً قے آجائے گی.لیکن مسلمان اور انگریز کو کچھ نہیں ہو گا.وہ کہتے ہیں ا گر یہ ضمیر کی آواز ہو تی تو ایک انگریز یا مسلمان کو قے کیوں نہ آتی.یا مثلاً سؤر انگریز کھاتا ہے یہودی اور مسلمان نہیں کھاتا اگر اس کے سامنے سؤر کا ذکر آجائے تو وہ تھو تھو کرنے لگتا ہے لیکن انگریز اور سکھ تھو تھو نہیں کرتا بلکہ اسی وقت اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہےکہ میں اس چیز کو استعمال کروں.اگریہ طبعی چیز ہو تی تو ایک انگریز کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی.ایک یہودی کے دل میں بھی پیدا ہوجاتی.ایک مسلمان کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی.
Page 532
ایک ہندو کے دل میں بھی پیدا ہو جاتی مگر نہیں پیدا ہوتی.جس کے معنے یہ ہیں کہ طبیعت میں کوئی خاص مادہ نہیں بلکہ جو کچھ ہے عادت اور رسم و رواج کی وجہ سے ہے.چونکہ ایک کو عادت ہو تی ہے سؤر نہ کھانے کی اس لئے سؤر کے ذکر پر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور چونکہ دوسرے کو عادت ہو تی ہے سؤرکے استعمال کی اس لئے اس کے دل میں کوئی نفرت پیدا نہیں ہو تی.اگر اس کے الٹ ہو تا تونتیجہ بھی اس کے خلاف رو نما ہو تا.مثلاً اگر ہندوؤں میں گائے کھانے کا رواج ہو تا اور انگریزگائے سے پر ہیز کرتے تو یہی بات آج الٹ ہو جاتی ہندوگائے کے گوشت سے کبھی برا نہ مناتے اور انگریز گائے کے گوشت کا ذکر سن کر ہی تھو تھو کرنے لگ جاتے اسی طرح وہ کہتے ہیں اگر مسلمانوں میں سؤر کا رواج ہو تا تو ان کو بھی یہ بات بری نہ لگتی.پس یہ طبیعت کی بات نہیں عادت کی بات ہے.جس بات کے کرنے کی انسان کو عادت ہو تی ہے اس پر وہ برا نہیں مناتا اور جس بات کی انسان کو عادت نہیں ہو تی اس پر وہ برا مناتا ہے لیکن یہ بات درست نہیں.اوّل تو ا س قسم کی مثالیں حقیقت کو ثابت نہیں کرتیں.سوال گائے کے گوشت اور سؤر کے گوشت کا نہیں.اس کو کوئی بھی طبعی نہیں کہتا یہ مذہبی احکام ہیں اور مذہبی احکام اور طبعی احکام میں فرق ہو تا ہے.یہاں سوال نفس لوّامہ کا ہے شریعت کا نہیں سؤر اور گائے کا تعلق شریعت سے ہے نفس لوّامہ سے نہیں.ہم تو خود مانتے ہیں کہ چونکہ گائے کا گوشت مسلمانوں میں جائز ہے اس لئے اس کا استعمال مسلمانوں کو برا نہیں لگتا اور چونکہ گائے کا گوشت ہندوؤں میں ناجائز ہے اس لئے انہیں اس کا ذکر برا لگتا ہےیا سؤر کا گوشت چونکہ مسلمانوں میں جائز نہیں اس لئے مسلمانوں کو اس کا ذکر بر الگتا ہے اور چونکہ سؤر کا گوشت عیسائیوں میں جائز ہے اس لئے انہیں اس کا ذکر برا نہیں لگتا.یہ درست ہے بلکہ ہم خود اس بات کے قائل ہیں کہ شرعی احکام کو برا یا بھلا ماننا فطرت پر دلالت نہیں کرتا یہ شریعت کی تفصیلات ہیں جن کو انسان اچھا یا برا سمجھنے پر مجبور ہو تا ہے.جس چیز کو ہم نفس لوّامہ کہتے ہیں وہ اخلاقی پابندیاں ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں.ہر قوم میں ان کا وجود پایا جاتا ہے.مثلاً گائے یا سؤر کے متعلق ہم مان لیتے ہیں کہ ان کا خاص قوموں کے ساتھ تعلق ہے لیکن جھوٹ بولنا، فریب کرنا، ریا کاری کرنا، احسان فرا موشی کرنا، قومی غداری کرنا یہ کسی قوم سے مخصوص نہیں.جہاں تک شریعت کے احکام کا تعلق ہےمسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے گھبراہٹ ہو تی ہے روزہ نہیں رکھتا تو اسے گھبراہٹ ہو تی ہے بلکہ اگر وہ بیمار بھی ہو تا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غلطی سے روزہ رکھ لیتا ہے.اسی طرح ہندوؤں میں شرادھ وغیرہ کی قسم کے شرعی احکام پائے جاتے ہیں یا بعض قسم کے روزے ان میں پائے جاتے ہیں یا مردے کا جلانا ہے.ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ طبعی احکام ہیں.مردے کا جلانا طبعی نہیں بلکہ شرعی امر ہے اگر مسلمانوں میں جلانے کا
Page 533
اور ہندوؤں میں دفنانے کا رواج ہو تا تو یہ اس پر خوش ہو تا اور وہ اس پر خوش ہو تا.ہم جب اس نفس لوّامہ کا ذکر کرتے ہیں جو شریعت کے بغیر بھی انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے تو ہم نیکی سے مراد اس وقت شرعی احکام نہیں لیتے بلکہ اخلاق مراد لیتے ہیں.پس یہ نفس لوّامہ شریعت کے احکام سے تعلق نہیں رکھتا.ضمیر شریعت کے احکام سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ان طبعی نیکیوں سے تعلق رکھتی ہے جو تمام مذہب میں تسلیم شدہ ہیں.یہ فرق تو ضرور ہے کہ مسلمان کہے گا اس طرح نماز پڑھو اور ہندو کہے گا اس طرح پڑھو مگر کیا کوئی مذہب ایسا بھی نظر آسکتا ہے جو یہ کہے کہ سچ نہ بولو.ایسے مذہب تو ضرور ہیں جو ایسی باتیں کہلواتے ہیں جو جھوٹی ہو تی ہیں مگر منہ سے وہ یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولو.یہ ضرور ہے کہ بعض مذاہب کی طرف ظالمانہ تعلیمیں منسوب کی گئی ہیں.مثلاً یہ کتنا بھیانک عقیدہ ہے جومسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہو تو اسے مار ڈالو.یہ اسلام کی تعلیم نہیں.مسلمانوں نے اسلام کی طرف منسوب کر دی ہے لیکن کسی مسلمان مولوی سے پوچھ دیکھو کہ کیا قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ ظلم کرو یا یہ آتا ہے کہ ظلم نہ کرو؟ تو وہ یہی جواب دے گا کہ قرآن کریم کی تعلیم یہی ہے کہ ظلم نہ کرو مگر وہ بعض ظالمانہ کام غلطی سے اسلام کی طرف منسوب کر دے گا.اسی طرح ہندو مذہب بیسیوں باتیں ایسی بتائے گا جو ظالمانہ ہوں گی.لیکن جب پوچھو تو سارے پنڈت یہی کہیں گے کہ ہمارے مذہب کا حکم یہی ہے کہ ظلم نہ کرو.غرض شریعت کے احکام میں تو اختلاف ہو جاتا ہے لیکن طبعی اصول میں اختلاف نہیں ہوتا.کوئی زرتشتی، ہندو، عیسائی یا کسی اور مذہب کا پیرو یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے مذہب میں یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ امن سے نہ رہو، خیانت کرو، جھوٹ بولو، ظلم کرو، یہ اصولی نیکیاں ہیں اور انہی سے نفس لوّامہ کا تعلق ہے.ان امور کے بارہ میں خود بخود انسان کی حالت اسے مجبور کر دیتی ہے اور کسی نہ کسی وقت وہ اپنے افعال پر شرمندہ ہوجاتا ہے.حضرت خلیفۂ اوّل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک چور علاج کے لئے آیا.آپ بڑے پایہ کے طبیب تھے اور ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے رہتے تھے.آپ نے اسے فرمایا کہ تم نے یہ کیا گناہ کا طریق اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا مال لوٹتے اور اپنےگھر میں حرام مال ڈال لیتے ہو.اس نے کہا واہ مولوی صاحب ہم حرام کماتے ہیں.ہمارے مال سے زیادہ حلال روزی اور کس کی ہو سکتی ہے ہم رات کو جاتے ہیں اپنی جان کو خطرہ میں ڈالتے ہیں اور جب لوگ سو رہے ہو تے ہیں ہم محنت و مشقت کر تے ہیں آخر محنت سے ہی رزق حلال ہو تا ہے.آپ نے فرمایا اس کے جواب سے میں نے سمجھ لیا کہ اس کی فطرت صحیحہ دب گئی ہے.چنانچہ میں نے اس سے اور باتیں شروع کر دیں.پھر کچھ عرصہ کے بعد جب پہلی بات سے اس کا ذہن ہٹ گیا میں نے ا س سے پو چھا
Page 534
چہارم.طہارت باطنی رکھنے والے پنجم.شرک سے پاک عربی زبان میں صفائی اور پاکیزگی کے معنے ادا کرنے کے لئے سات الفاظ اور ان کے استعمال میں فرق عربی زبان میں پاکیزگی کے مفہوم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں نَظَا فَۃٌ.طَھَارَۃٌ.طِیْبَۃٌ.نَقَاءٌ.زَکَاءٌ.صَفَاءٌ.نَزَاھَۃٌ ان میں سے طہارت جسمی اور نفسی ہوتی ہے یعنی نجس کے مقابل پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.قرآن کریم میں پانی کو طہور کہا گیا ہے لیکن اس کے مقابل میں مٹی کو طیّب کہا گیا ہے چنانچہ فرماتا ہے.وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا( الفرقان:۴۹) لیکن مٹی کے متعلق فرماتا ہے کہ فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ( المائدۃ:۷) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ طَھِّرْ بَیْتِیَ ( الحج:۲۷) لیکن عربی محاورہ کے مطابق یہ نہیں کہا جائے گاکہ طَیِّبْ بَیْتِیَ.اس سے معلوم ہوتا ہے کہ (۱) طہارت میں خارجی نجاست کے دُور کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسی طرح تَطْہِیْـر کے معنے خارجی نجاست خواہ جسمانی ہو یا روحانی اس کو دُور کرنے کے بھی ہوتے ہیں لیکن طِیْبَۃٌ کا لفظ ذاتی جوہر کی طرف اشارہ کرتا ہے خارجی نجاست کی طرف نہیں.چنانچہ طَھِّرْ کے معنے تو صاف کرنے کے ہوتے ہیں لیکن طَیِّبْ کالفظ جب ایک عرب بولے گا تو خارجی نجاست کو دُور کرنے کے معنوں میں وہ اسے کبھی استعمال نہیں کرے گا بلکہ اس کے معنے مزیدار یا اچھا بنانے یا مزیدار یا اچھا پانے کے ہوتے ہیں چنانچہ طَیَّبَ الشَّیْءَ کے یہ معنے نہیں ہوں گے کہ اُس نے نجاست ظاہری دُور کر دی بلکہ طیّب ہمیشہ مزیدار یا اچھا بنانے یا مزیدار یا اچھا پانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے مثلاً طَیَّبَ اللَّحْمَ کے معنے ہوتے ہیں اس نے گوشت اچھا پکایا اور اسے مزیدار بنایا.یا اس کے یہ معنے ہوں گے کہ اُس نے گوشت کو اچھا پایا کھانا کھایا تو کہا کہ کھانا بڑا اچھا پکایا گیا تھا یا خوب مزیدار تھا.اگر زمین پر بوٹی گر جائے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ طَھِّرْ اس بوٹی کو صاف کرو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ طَیِّبْ.لیکن اچھا پکانے یا اچھا پانے کے مفہوم کو جب ہم ادا کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے طَھِّرْ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے.اسی طرح طَیِّبْ کے معنے امن یا سکون دینے کے بھی ہوتے ہیں یعنی اصلاحِ نفس کے.پس طَھَارَۃٌ اور طِیْبَۃٌ میں یہ فرق ہے کہ طہارت نجاست خارجی سے حفاظت پر دلالت کرتی ہے.مگر طیبہ صرف ذاتی خوبی پر دلالت کرتی ہے جیسے مزا، خوبصورتی، مٹھاس یا کسی چیز کا فائدہ بخش ہونا.ایک میٹھی اور مزیدار شے کو ہم طیّب کہیں گے طاہر نہیں کہیں گے یامثلاً کوئی چیز خوبصورت ہو یا مفید ہو تو ہم اس کو طیّب تو کہیں گے مگر طاہر
Page 535
سے نفرت کو طبعی سمجھ لیا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی فطرت کا حصہ نہیں بلکہ عادت سے تعلق رکھنے والے امور ہیں.ہم کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں.یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نفس لوّامہ مر جاتا ہے.نفس امّارہ آخر اسی وقت پیدا ہو گا جب نفس لوّامہ مر جائے گا.اگر بار بار خیانت کروائی جائے گی تو یقیناً خیانت کااحساس دل میں سے مٹ جائے گا اور اگر بار بار جھوٹ بلوایا جائے گا تو جھوٹ کا احساس دل میں سے مٹ جائے گا.مگر سوال یہ نہیں کہ کسی کو عادت ڈال ڈال کر کوئی فعل کروایا گیا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ جو باتیں مختلف مذاہب اور مختلف ممالک اور مختلف حالات میں تمام بنی نوع انسان میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں وہ عادت یا رسم و رواج کے ساتھ تعلق رکھنے والی کس طرح قرار دی جا سکتی ہیں.دنیا میں جو بڑے بڑے برّ اعظم ہیں ان میں ایشیاہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، افریقہ ہے، جنوب مشرقی جزائر ہیں.ان کی زبانوں میں کتنا بڑا فرق ہے.ہندوستان میں ہی بیسیوں زبانیں بولی جاتی ہیں.بلوچیو ں سے پوچھ لو تو ان کی ہی کئی زبانیں نکل آئیں گی.پٹھانوں کی زبان لے لو تو وہ ہماری زبان سے الگ ہے.بنگالی زبان دیکھو تو وہ اور قسم کی ہے.پھر جب ہندوستان سے باہر چلے جاؤ تو زبانوں کا اتنا بڑا اختلاف نظر آئے گا کہ حیرت آجائے گی چینی اور زبان استعمال کر تے ہیں.روسی اور زبان استعمال کرتے ہیں.افریقہ کے حبشی بالکل اور زبان میں باتیں کرتے ہیں.ذرا بھی تو ان کی ہماری زبان کے ساتھ کوئی مشابہت نظر نہیں آتی.پھر امریکہ کے ریڈ انڈینز کو دیکھو ان کی زبان اور ہے.کتنا اختلاف زبانوںمیں پایا جاتا ہے.اس کے بعد مذہبوں کو دیکھو تو ان میں عظیم الشا ن اختلاف نظر آئے گا.افریقہ میں چلے جاؤ تو تمہیں تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر مذہبوں کا فرق دکھائی دے گا.جزائر میں چلے جاؤ تو وہاں مذاہب کا اختلاف نظر آئے گا.اب سوال یہ ہے کہ طبعی نیکیوں سے لگا ؤ اگر صرف مذہب کا نتیجہ ہے تو وہ چیز تو بدل گئی.تم کہتے ہوکہ چونکہ مذہب نے جھوٹ کے خلاف تعلیم دی تھی اس لئے لوگ جھوٹ سے نفرت کرنے لگے یا چونکہ مذہب نے امانت کے متعلق تعلیم دی تھی اس لئے انہیں امانت کی عادت پڑ گئی.ہم کہتے ہیں کہ اسی مذہب نے خدا کے متعلق بھی سمجھایا تھا.رسول کے متعلق بھی سمجھایا تھا.کتاب کے متعلق بھی سمجھایا تھا.مگر چین والا کچھ کہتا ہے ،منگولیا والا کچھ کہتا ہے، آسٹریلیا والا کچھ کہتا ہے ،ریڈ انڈینز کچھ کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی کچھ کہتے ہیں.جب اور سب چیزیں بدل گئیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں نہ بدلیں.صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ مذہب کا حصہ نہیں بلکہ فطرت کا حصہ ہیں.مذہب کا حصہ بد ل گیا اور فطرت قائم رہی.غرض مختلف مذاہب، مختلف زبانوں، مختلف رسم و رواج اور مختلف عادات کا پیدا ہو جانااور پھر طبعی نیکیوں میں ان کا آپس میں اشتراک رہنا بتاتا ہے کہ فطرت سے تعلق رکھنے
Page 536
والے امور اور ہیں اور شریعت سے تعلق رکھنے والے امور اور ہیں.ساری دنیا میں زبانیں بدلیں، رسم و رواج بدلے، حالات اور واقعات بدلے مگر سچ اور جھوٹ کو اچھا یا برا سمجھنے کااحساس ایک ہی رہا.امانت اور دیانت کو برا یا اچھا سمجھنے کا احساس وہی رہا.فجی میں بعض ایسے لوگ اب تک پائے جا تے ہیں جو ماں باپ کو مار کر کھا جاتے ہیں.یہ کتنا بڑا فرق ہے جو ان میں اور دوسرے لوگوں میں پایا جاتا ہے.اسی طرح معیار زندگی کو لے لو تو اس میں اختلاف ہوگا.شادی بیاہ کے معاملے کو لے لو تواُس میں اختلاف ہوگا.موت کے معاملات کو لے لو تو اس میں اختلاف ہوگا کوئی مردہ کو دفن کرتا ہے کوئی جلاتا ہے اور کچھ ایسے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں جو ماں باپ سے پیار کی یہ علامت سمجھتے ہیں کہ بیمار ہو نے پر انہیں ذبح کر کے کھا لیتے ہیں.وہ کہتے ہیں کہ ما ں باپ پر ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں کھائیں ان کے گوشت کو ضائع کیوں ہو نے دیں.مگر سچ اور جھوٹ کے متعلق ایک افریقہ کے حبشی سے پو چھو، جاپانی سے پوچھو، چینی سے پو چھو، امریکہ کے ریڈ انڈینز سے پوچھو، فن لینڈ کے رہنے والوں سے پوچھو،سوئٹزر لینڈ کے رہنے والوں سے پو چھو، ناروے کے رہنے والوں سے پو چھو ،افریقن قبائل سے پوچھو تو یہ سارے کے سارے زبانوں اور رسم و رواج اور طرز رہائش کے اختلاف کے باوجود اس بات میں کلّی طور پر متفق ہوں گے کہ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بُری چیز ہے.امانت سے کام لینا چاہیے خیانت اور بد دیانتی سے بچنا چا ہئے.یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ آواز فطرت انسانی کی آواز ہے کیونکہ مذاہب بدل گئے لیکن یہ چیز نہیں بدلی.رسم و رواج کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور بد ل گئے.زبانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور بدل گئے.مگر یہ امور نہ بدلے.پس زبانوں، ملکوں اور مذہبوں کے بدل جانے کے باوجود ان باتوں کے نہ بدلنے کےیہ معنے کیوں نہ لئے جائیں کہ یہ جذبات عادات کا نتیجہ نہیں بلکہ عادات ِ قومی ان جذبات کا نتیجہ ہیں.یورپ کا فلاسفر کہتا ہے کہ عادات کے نتیجہ میں یہ جذبات پیدا ہوئے ہیں.ہم کہتے ہیں اگر اس کے نتیجہ میں یہ جذبات پیدا ہوتے تو ضروی تھا کہ عادات کے مختلف ہو نے سے ان میں بھی اختلاف پیدا ہو جاتا مگر چونکہ ان میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے ہم بجائے یہ تسلیم کرنے کے کہ عادات کے نتیجہ میں یہ جذبات پیدا ہوئے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عادات قومی ان جذبات کے نتیجہ میں پیدا ہوئے ہیں.غرض ہر ملک اور ہر قوم میں یہاں تک کہ جا ہل سے جاہل اقوا م میں بھی سچائی اور دیانت اور امانت اور عدل اور انصاف اور رحم اور ایسی ہی دوسری خوبیوں کی برتری کا احساس پایا جاتا ہے.میں نے مختلف مذاہب اور قوموں کے اخلاق کا مطالعہ کیاہے اور اس بارہ میںبعض بڑی بڑی کتب پڑھی ہیں.پرانی سے پرانی قوموں کے اخلاق کا بھی میں نے مطالعہ کیاہے اور ان قبائل کے عادات کا بھی مطالعہ کیا ہے جو اب بھی جنگلوں میں ننگے رہتے ہیں اور
Page 537
انسانوں کے قریب نہیں پھٹکتے.اگر کوئی آدمی انہیں نظر آئے تو بسا اوقات وہ اسے تیر مار کر ہلاک کر دیتے ہیں.میں نے ان سب اقوام اور لوگوں کے حالات کا مطالعہ کر کے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ کچھ اخلاق کے اصول ایسے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں اختلافات کے باوجود یہ لوگ ان اصول میں متحد ہیں اور دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا.حقیقت یہ ہے کہ مختلف اقوام میں گناہوں سے بچنے کا احساس درحقیقت نتیجہ ہے نفس لوّامہ، کانشنس یا ضمیر کا.یہ قومی رسم و رواج کانتیجہ نہیں.پس جو شخص بھی نفس لوّامہ کی طاقت کا قائل ہو گا لازمی بات ہے کہ وہ اس کی آواز کو سنے گااور گناہ سے بچ جائے گا.میں نے بتایا ہے کہ یورپ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے جو باتیں انسان نے اپنے باپ دادا سے سنی ہوئی ہوتی ہیںا ن کو کرنے لگ جاتا ہے اور جن باتوں سے اسےمنع کیا جاتا ہے ا ن کی نفرت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے ضمیر یا فطرت کی کوئی آواز نہیں ہوتی جو اسے برائیوںپر ملامت کرے.اللہ تعالیٰ اسی بات کا اس آیت میں ذکر کر تے ہوئے فرماتا ہے کہ جو بھی دِیْن یا وَرَع یعنی بدیوں سے بچنےکے احساس کامنکر ہو گا وہ بدیوںمیں مبتلا ہو جائے گا اور بہت سی نیکیوں سے محروم ہو جائے گا.فرماتا ہے اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ مجھےبتاؤ تو اس شخص کا حال جو ورع کامنکر ہے اور کہتا ہے کہ بدیوں سے احتراز کر نے کی خواہش طبعی تقاضا نہیں بلکہ ایک غیر فطرتی امر ہے جو شخص بھی یہ کہے گا اس کا کیریکٹر کمزور اور اس کے اخلاق خراب ہو جائیں گے اس کےمقابلہ میں جو شخص بھی وَرَع کاقائل ہو گا وہ نیکیوں میں ترقی کرتا چلا جائے گا.قرآن کریم میںاللہ تعالیٰ نے نفس لوّامہ کو اپنی ہستی کے ثبوت میں پیش کیا ہے اور اس میں کیا شبہ ہے کہ نفس لوّامہ کی پیدائش ایک خدائی تدبیر ہے.چونکہ انسان مختلف قسم کے ابتلاؤں میں پڑنے والا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ وہ بغیر حفاظت کے رہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہی ایک آواز رکھ دی.یہ فطرت کی آواز اسے ہمیشہ نیکی کی طرف کھینچتی رہتی ہے بسا اوقات وہ بدیوں کےمیدان میں بہت دور نکل جاتا ہے مگر پھر کسی وقت فطرت کی آواز اسے یک دم کھینچ کر نیکی کی طرف اس طرح لے آتی ہے کہ یوں معلوم ہو تا ہے وہ کبھی بدیوں میں مبتلا ہی نہیں ہوا تھا اور کبھی گناہوں کی شامت اسے نیکیوں سے بالکل محروم کر دیتی ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی انسان نیکیوں میں اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ یوں معلوم ہو تا ہے اب وہ کبھی بدی کے قریب بھی نہیں جائے گا مگر یک دم اسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ دوزخ میں جا پڑتا ہے اور کبھی وہ بدیاں کرتا چلا جاتا ہے اور ان بدیوں میں اتنی ترقی کر جاتا ہے کہ یوں معلوم ہو تا ہے وہ نیکی کے کبھی قریب نہیں آئے گا مگر یک دم اسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے(بخاری کتاب الجھاد والسیر باب لایقال فلانا شھید).
Page 538
آپؐکے اس قول کے مطابق ہمیں دنیا میں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں اور یہ فوری تغیّر بھی کسی غیر طبعی بات کا نتیجہ نہیں ہو سکتا.یقیناً اس کے پیچھے ایک طبعی مظاہرہ ہو تا ہے اور یہ اسی طاقت کا نتیجہ ہو تا ہے جو خدا تعالیٰ نے ہرانسان میں پیدا کی ہے اور جو اسے کھینچ کر کہیں سے کہیں لے جاتی ہے.ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک بہت بڑا رئیس تھا جو ہر وقت ناچ گانے اور شراب میں مشغول رہتا تھا اور اس کا دعویٰ تھا کہ چونکہ میرے بادشاہ اور حکام سے تعلقات ہیں اس لئے کوئی شخص مجھے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہم نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ ہمیشہ کہتا کہ تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو مجھے روکنے کی تم میں ہمت نہیں کیونکہ بالا حُکّام اور سرکاری افسران سے میرے خاص تعلقات ہیں.چونکہ رات اور دن ناچ گانے کا شغل برابر جاری رہتا تھا اور عبادت میں خرابی واقعہ ہو تی تھی اس لئے تنگ آکر میں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا.ایک دفعہ میں حج کے لئے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہی رئیس حج بیت اللہ کے لئے آیا ہوا ہے.اسے دیکھ کر میرے ہو ش اڑ گئے کہ ایسا بد معاش اور بے ایمان بھی حج کے لئے آنکلا ہے.میں نے آگے بڑھ کر اسے مصافہ کیا اور کہا یہ کیا بات ہے کہ آج تم حج کے لئے آئے ہوئے ہو.تمہاری خاطر تو ہم نے شہر ہی چھوڑ دیا تھا.تمہاری وجہ سے ہماری نمازیں خراب ہوئیں.تہجد پڑھنےمیں مزہ نہ آیا.دعاؤں کی طرف توجہ نہ ہو سکی کیونکہ ہر وقت گانے بجانے کاشور رہتا تھا آخر میں نے تنگ آکروہ شہر ہی چھوڑ دیا مگر جس شخص کو چھوڑ کر میںباہر نکلا تھا آ ج پھر وہ یہاں موجود ہے.میں نے ہر ممکن نصیحت جو میرے امکان میں تھی تمہیں کی.تمہیں قرآن سنایا تم پر اثر نہ ہو ا.حدیثیں سنائیں تم پر اثر نہ ہوا مگر آج یہ کیا معاملہ ہے کہ تم حج کے لئے یہاں موجود ہو ؟ اس نے کہا تم جو کچھ کہتے ہو درست ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ایک وقت مقدّر ہو تا ہے ایک دن عصر کے بعد شراب کا دور چل رہا تھا.صراحیوں پر صراحیاں لنڈھائی جا رہی تھیں.دوست اور ندیم بیٹھے تھے.گانا بجانا ہو رہا تھا اور میں چھت پر منڈیر کے قریب بیٹھا تھا کہ گلی میںسے کوئی آدمی گذرا جو یہ آیت پڑھتا جا رہا تھا کہ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ (الحدید:۱۷) کیا مومنوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ خدا کے خوف سے وہ گناہ کو چھوڑ دیں اور ذکر الٰہی میں مشغول ہو جائیں یہ آواز میرے کان میں پڑی تو یک دم میرے منہ سے چیخ نکل گئی.میں نے صراحیاں توڑدیں اور اپنے دوستوں سے کہا کہ تم اسی وقت میرے پاس سے چلے جاؤ.اس وقت میرے دل پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہو تا تھا کہ کوئی مسافر یہ آیت پڑھ رہا ہے بلکہ یوں معلوم ہو تا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جھانک کر کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے گناہوں سے باز نہیں آنا.اور میں نے سچی توبہ کی اور اس کے نتیجہ میں تم مجھے آج یہاں دیکھ رہے ہو(تذکرۃ الاولیاء صفحہ ۴۹ ، ۵۰) غرض ضمیر
Page 539
مردہ نہیں ہو تی وہ مسخ ہو سکتی ہے، وہ گناہوں سے دب سکتی ہے مگر مر نہیں سکتی.بہر حال ضمیر انسان کو ہلاتی رہتی اور اسے بیدار کرتی رہتی ہے جو شخص اس ضمیر کی آواز کو سن لیتا ہے.وہ نیکی کی طرف قدم اٹھانے لگ جاتا ہے اور جو اسے مردہ نہیں کرتا نیکیوں کا راستہ اس کے لئے کھلا رہتا ہے لیکن جو شخص ضمیر کو کچل دیتا یا مار ڈالتا ہے وہ بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.پس فرماتا ہے اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ.مجھے خبر تو دو اس شخص کے متعلق جو ضمیر کی آواز کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ یہ محض ڈھکوسلہ ہے تم دیکھو گے کہ ایساانسان قسم قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہو جائے گا اور نیکیوں سے محروم ہوجائے گا کیونکہ وہ ذریعہ جو نیکیوں کی طرف لے جانے والا تھا.اس کا اس نے استیصال کر دیا.الدّیْن کے نویں معنے عادت کے (۹) اَلدِّیْن کے ایک معنے عادت کے ہیں.عادت بھی انسا ن کو بدیوں سے بچانے میں بڑی ممد ہو تی ہے.سیاق و سباق کو مدّ ِنظر رکھنے سے معلوم ہو تا ہے کہ یہاں عادت سے مراد نیکی کی عادت ہے عام عادت اس سے مراد نہیں ہو سکتی یعنی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جسے گوشت کھانے کی عادت ہو گی وہ یتیموں پر ظلم نہیں کرے گا یا جسے انگریزی لباس پہننے کی عادت ہو گی وہ بدیوں سے محفوظ رہے گا.یہ بالکل بے معنی بات بن جاتی ہے.سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ اس جگہ عادت سے مراد نیکی کی عادت ہے اور اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ جو شخص اس اصل کو تسلیم کرتا ہے کہ عادت کا بھی انسانی ترقی میں بہت بڑادخل ہے اور عادت بھی نیکیوں میں ترقی کرنے اور بدیوں کے دبانے میں بہت بڑا حصہ رکھتی ہے وہ ترقی کر جاتا ہے.اور جو شخص عادت کی قوت کو نہیں مانتا وہ بدیوں میں مبتلا ہو جاتا اور نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے.یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس فلسفہ کو پیش کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جس قدر باتیں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے فائدہ اور نفع اور ترقی کے لئے رکھی گئی ہیں.یہ نکتہ دنیا میں صرف قرآن کریم نے ہی پیش کیا ہے.وہ کسی انسانی جذبہ کے متعلق یہ نہیں مانتاکہ وہ بے کار اور لغو ہے بلکہ وہ اصرار کرتا ہے کہ ہر جذبہ جو انسانی فطرت میں پایا جاتا ہے وہ اپنے اندر حکمت رکھتا ہے اور انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے.سارا قرآن اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز لغو پیدا نہیں کی بلکہ جو کچھ پیدا کیا ہے تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کیا ہے.حتی کہ وہ بعض دفعہ مثالوں سےبتاتا ہے کہ موت جس سے تم ڈرتے ہو وہ بھی تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے.ابتلاء جس سے تم خوف کھاتے ہو وہ بھی تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کئے گئے ہیں.غرض اصرار اور تکرار سے وہ اس بات کو پیش کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے انسانی فائدہ کےلئے پیدا کی ہے مضرّت اور نقصان کے لئے پیدا نہیں کی.مضرّت اور نقصان اس کے غلط استعمال
Page 540
سے پیدا ہو تا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک ریشمی جبّہ آیا.آپ نے حضرت عمر ؓ کو بلوا کر وہ جبّہ انہیں تحفۃً دے دیا.نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر ؓ وہی ریشمی جبّہ پہنے آگئے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ کے چہرہ پر خفگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا.عمر تم نے یہ کیا کافروں والا لباس پہن رکھا ہے.حضرت عمر ؓ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہی تو یہ جبّہ مجھے دیا تھا اور اب آپ ہی میرے پہننے پر اظہار ناراضگی فرما رہے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.یہ تمہارے استعمال کے لئے تو نہیں تھا.تمہاری بیوی بچے بھی تھے تم اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو دے سکتے تھے تمہیں یہ کس نے کہا تھا کہ تم خود اسے پہن لو(مسلم کتاب اللباس والزینۃ باب تـحریم لبس الحریر...).اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ریشمی جبّہ دیا آپ اس کے دینے سے انکار نہیں کرتے مگر فرماتے ہیں یہ اور کام کے لئے تھا تم اپنی بیوی کو پاجامہ یا کرتا بنوا دیتے یا بیٹی کے لئے کوئی کپڑا سلوا لیتے، خود کیوں پہنا.تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی پیدا نہیں کی جو انسانی فائدہ کے لئے نہ ہو.ہاں ہر چیز کے الگ الگ کام ہیں مثلاً سونا خدا تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے مگر دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں سونا جمع کریں گے انہیں قیامت کے دن وہی سونا گلا گلا کر جسم پر داغ دیئے جائیں گے.اب بظاہر یہ بات عجیب معلوم دیتی ہے کہ خود ہی سونا پیدا کیا ہے اور خود ہی اس کے استعمال پر سزائیں تجویز کر دی ہیں اس کا جواب یہی ہے کہ سونا خدا تعالیٰ نے جمع کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا بلکہ اسے تجارت اور اقتصادی امور میں لینے دینے کے لئے پیدا کیا ہے.اسی طرح اپریشن میں ہڈیوں کے جوڑ نے اور دانتوں کے جو ڑنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ سونا ایسی دھات ہے جسے سب سے کم زنگ لگتا ہے.اس لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ اس سے زیور بنوا بنوا کر رکھ لئے جائیں.سوائے اس کے کہ تھوڑے سے زیور عورت زینت کے طور پر استعمال کرے.غرض ہر چیز کسی فائدہ کے لئے پیدا کی گئی ہے.انہی میں سے عادت بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا انسانی ترقی کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے.بعض لوگ کہتے ہیں کہ عادت بری چیز ہے.اچھی عادت بھی بری ہے اور بری عادت بھی بری ہے.وہ کہتے ہیں جب کسی نیک کام کی بھی عادت ہو جائے تو انسان کو کیا ثواب مل سکتا ہے.مگر یہ درست نہیں.دنیا میں عادت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے.عادتوں کے ذریعہ نیکی کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے اگر عادت نہ ہوتی تو یہ سفر اتنا آسان نہ ہوتا.عادت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہر اگلے عمل کو انسان کے لئے آسان کر دیتی ہے.عربی میں مثل ہے کہ اَلْعَوْدُ اَحْـمَدُ یعنی جب تم کوئی کام کرو تو پھر اسے دہراؤ اور یاد رکھو کہ جتنی دفعہ تم کوئی کام دہراؤ گے اتنا ہی وہ اچھا ہو جائے گا.ہم سوئی داگا لے کر بیٹھ جائیں اور کپڑا سینے لگیں تو شاید ایک معمولی کپڑا سینے میں
Page 541
ہی ہمیں پانچ دن لگ جائیں اور پھر اس کی سلائی یوں معلوم ہو گی جیسے کوئی چیونٹا چل رہا ہے لیکن درزی اسی کپڑے کو شام تک سی دے گا.اب ایک درزی کو ہم پر کیا فو قیت ہے یہی فوقیت کہ اس نے کپڑے سینے کی عادت ڈالی ہوئی ہے یہی حال اور کاموں کا ہے.مثلاً سائیکل کی سواری ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ سائیکل چلانا نہیں بھولتا مگر میں تو بھول گیا.کئی سالوں کے بعد میں ایک دن گھر میں سائیکل چلانے لگا تو گر پڑا ہاں تیرنا نہیں بھولا.۲۵ سال کے بعد بھی میں تیرا تو تین میل تک مسلسل تیرتا چلا گیا.بہر حال سائیکل کی سواری لے لو یا تیرنا لے لو اس میں بھی مشّاق نکل جاتے اور دوسرے لوگ رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں تیرنے یا سائیکل چلانے کی عادت ہو تی ہے.دنیا میں لوگ سفر کرتے وقت پو چھا کرتے ہیں کہ کوئی اچھا موٹر چلانے والا ہے.کبھی پو چھتے ہیںیہاں کوئی اچھا طبیب ہے ؟ اچھا موٹر چلانے والا کون ہو تا ہے وہی جسے موٹر چلانے کی عادت ہو تی ہے.اچھا طبیب کون ہو تا ہے وہی جسے علاج کرنے کی دیرینہ عادت ہو تی ہے، اچھا سرجن کون ہو تا ہے وہی جسے اپریشن کرنے کی دیرینہ عادت ہو تی ہے.اچھے استاد کے کیا معنے ہو تے ہیں یہی کہ جس نے سال ہا سال تک پڑھایا ہو.اچھے باورچی کے کیا معنے ہو تے ہیںیہی کہ جس نے سالہا سال کھانا پکایا ہو.بے شک ان کاموں میں عقل بھی دخل رکھتی ہے مگر عادت کا بھی بہت بڑا حصہ ہے.غرض جو کام بھی دنیا میں نظر آتے ہیں.جس قدر پیشے اور فنون نظر آتے ہیں ان میں مہارت محض عادت سے پیدا ہو تی ہے عادت کو نکال دو تو کوئی مہارت پیدا نہیں ہو سکتی.یہ کہنا کہ عادت بری چیز ہے حماقت ہے.عادت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے.کہتے ہیں ع کسب کمال کن کہ عزیز جہان شوی اس کے معنے بھی یہی ہیں کہ عادت پیدا کرو.غرض دنیا کے ہر فن کی ترقی عادت کے ساتھ وابستہ ہے.ہر عمل جو تم کرتے ہو وہ ویسا ہی دوسرا عمل تمہارے لئے آسان کر دیتا ہے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتےہیں کہ جب کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو فرشتے ایک سفید نقطہ اس کے دل پر لگادیتے ہیں اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو فرشتے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں.اسی طرح سیاہ اور سفید نقطے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن سفید نقطے سیاہ نقطوں پر غالب آجاتے ہیں اور وہ بدیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے یا سیاہ نقطے سفید نقطوں پر غالب آجاتے ہیں اور وہ نیکیوںسے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے(مسلم کتاب الایمان باب بیان ان الاسلام بدأ غریبًا و سیعود غریبًا).اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نیکی کی عادت آہستہ آہستہ اسے ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ بدی اسے ایسی معلوم ہو تی ہے جیسے سمندر کی مچھلی جنگل میں پھینک دی جائے.یا بدی کرتے کرتے وہ ایسا عادی
Page 542
ہوجاتا ہے کہ نیکی کرنا اسے ایسا ہی معلوم ہو تا ہے جیسے سمندر کی مچھلی کو خشکی میں پھینک دیا جائے.نیکی کے میدا ن میں اگر اسے لایا جائے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ ایک قدم بھی چلنے کی اپنے اندر طاقت نہیں پاتا.یہ عادتوں ہی کا اثر ہوتا ہے ورنہ اور کوئی بات نہیں ہو تی.سپاہی ہمارے ملک کا ایک اہم ترین حصہ ہے لیکن سپاہی کیوں بہادر سمجھا جاتا ہے اسی لئے کہ اسے ہتھیار چلانے کی عادت ہو تی ہے.واٹر لو میں جب نیپولین کی انگریزوں سے جنگ ہوئی تو ایک بہت ہی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے نیپولین کی فوجوں کو شکست ہو گئی.نیپولین کا ایک جر نیل تھا جو تھا تو بڑا بہادر مگر اس سے ایک غلطی ہو گئی.اسے آ گے بڑھ کر واٹر لو کی پہاڑی پر قبضہ کرنےکا حکم تھا وہ منزل مارتا ہوا وہاں پہنچا تو سپاہیوں پر ترس کھا کر اس نے انہیں پہاڑی کے نیچے آرام کرنے کا حکم دے دیا.اور سمجھا کہ صبح پہاڑی پر قبضہ کر لیں گےمگر نیپولین کو کہلا بھیجا کہ پہاڑی پر قبضہ ہو گیا ہےرات کو برطانوی فوجوں نے واٹر لو کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا.صبح جرنیل نے یہ حال دیکھا تو اپنی بات سچی کرنے کے لئے متواتر انگریزی فوج پر حملےکئے مگر کامیا ب نہ ہوا بلکہ اپنی فوج تباہ کر لی.صبح نیپولین پہنچا تو مجبوراً اسے لڑنا پڑا مگر پہاڑی کی وجہ سے اس کی فوج غالب نہ آسکی.جس فوج کو پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لئے بھجوا یا گیا تھا نیپولین کی خاص پسندیدہ فوج تھی.جب بار بار حملوں سے اس فوج کا گولہ بارود ختم ہو گیا خود بڑے لشکر کو بھی شکست ہو گئی تو ایک افسر اس فوج کے پاس سے گذرا اور ان سے کہا کہ فوج کو شکست ہو گئی ہے تم کیوں نہیں بھاگتے تو انہوں نے کہا کہ نیپولین نے ہمیں بھاگنا سکھایا ہی نہیں.(Nepoleon as Military commander, General Sir James Marshall.Cornwall B.t P.62,96) مطلب یہ تھا کہ نیپولین نے ہمیں لڑنے کی عادت ہی ڈالی ہے بھاگنے کی نہیں.غرض عادت دنیا کی اہم ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے وہ چیز جسے ماحول کےمطابق ہوجانا کہتے ہیں درحقیقت عادت کاہی دوسرا نام ہے.جب پودوں کو ایک خاص زمین میں کچھ مدت رہنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے تو وہ پودے اس زمین کے ساتھ ایک خاص مناسبت پیدا کر لیتے ہیں اور زیادہ بہتر فصل پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ پودے اس ملک کے لحاظ سے کچھ نئی خصوصیات بھی پیدا کرلیتے ہیں.یہی حال جانوروں کا ہے.اسی طرح جب انسانوں کو نئی قسم کی عادتیں ڈال دی جائیں تو نئی قسم کے انسان پیدا ہو نے لگ جاتے ہیں.اگر عادت کے قانون پر لوگ غور کریں اور اعلیٰ درجہ کی عادات اپنےاندر پید اکرنے کی کوشش کریں تو یقیناً آئندہ نسلیں نہایت اعلیٰ درجہ کی پید اکی جا سکتی ہیں.یقیناً انسان برتر (جسے امریکن super man کہتے ہیں) پیدا کئے جا سکتے ہیں بشرطیکہ لوگ عادت کے فلسفے پر غور کریں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں.مگر افسوس ہے کہ لوگ اپنی نسلوں کوخودرَو پودوں کی طرح بغیرکسی حفاظت اور نگرانی
Page 543
کے چھوڑ دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ اچھا ہو تا ہے تو بیٹا خراب ہو جاتا ہے.پھر عادتیں پیدا ہوتی ہیں سوسائٹی سے اچھے سے اچھا آدمی بھی اپنی اولاد کی تربیت میں قطعی طور پر ناکام رہے گا اگر اس کاماحول اچھا نہیںاور اگر اس کے ارد گرد رہنے والے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اور اعلیٰ درجہ کی عادات اپنے اندر رکھنے والے نہیں اگر ساری قوم مل کر اپنی عادتوں کی اصلاح کرے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ آئندہ نسل ایسی اعلیٰ درجہ کی پیدا ہو گی جس کا چلن نہایت مضبوط ہو گا.جس کے اخلاق نہایت بلند ہوں گے اور جس کا جذبہ ٔملّت اتنا اعلیٰ درجے کا ہو گا کہ دنیا کی کوئی قوم اس کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکے گی.یوروپین قوموں کے سکولوں میں اس امر کو خصوصیت سے مدّ ِنظر رکھا جاتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے قومی چلن کو ترقی دیں.یورپ کے لوگ جب بھی انصاف کا ذکر کریں گے ہمیشہ کہیں گے یہ کرسچن سویلیزیشن ہے یاکرسچن سویلیزیشن کا تقاضا یوں ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج کل یورپ جس اعلیٰ مقام اخلاق پر پہنچا ہوا ہے اس کے رو سے ایسا ہو نا ضروری ہے حالانکہ وہ اعلیٰ مقام اخلاق تو کیا ابھی اس مقام کے ادنیٰ ترین معیار تک بھی نہیں پہنچا جو اسلام نے مقرر کیا ہے مگر بار بار کر سچن سویلیزیشن کی اصطلاح استعمال کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض مسلمان بھی دوران جنگ میں تقریریں کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جرمن کرسچن سویلیزیشن کے خلاف چل رہا ہے حالانکہ ان بے چاروں نے انجیل کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی مگر کرسچن سویلیزیشن کا شور مچاتے چلے جاتے تھے.غرض یوروپین قومیں اپنی قومیت کی برتری ثابت کرنے کے لئے نوجوانوں میں احساس برتری پیدا کرتی رہتی ہیں اور ا سی احساس کی بیداری کے لئے انہوں نے یہ اصطلاح قائم کی ہے مگر بعض احمق مسلمان بھی ان کی نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اخلاق برے ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہیں.حقیقت یہ ہے کہ عادت ایک بڑی طاقت ہے جو قومیں اس نکتہ کو سمجھتی ہیں وہ بہت بڑا فائدہ اٹھا لیتی ہیں اور جو اس کو نہیں سمجھتیں وہ نوجوانوں کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دیتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آوارہ ہو جاتے ہیں.اسی طرح جو فرد اس نقطہ کو سمجھے گا کہ نیکی کی عادت ایک عظیم الشان نعمت ہے وہ اس سےزیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور جو اس نکتہ کو کوئی وزن نہیں دے گا وہ نیکیوں سے محروم ہو جائے گا.حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا تو اس نے ہزاروں ہزار نیکیاں پیدا کردیں اور ان نیکیوں کا غلط استعمال بدیاں بن گیا جب ہم افراد کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہو تا ہے کہ ان کا بھی بعض نیکیوں پر قبضہ
Page 544
ہو تا ہے اور بعض پر نہیں چنانچہ اپنے لوگوں میں ہی غور کر کے دیکھ لو.ایک شخص جھوٹ فوراًبو ل دے گا لیکن خیانت نہیں کرے گا.ایک اور شخص مال اڑانے سے دریغ نہیں کرے گا مگر سچ بولے گا.کوئی شخص گالی نہیں دے گا مگر تھپڑ رسید کردے گا.دوسرا مارے گا نہیں مگر اٹھتے بیٹھتے گالیاں دیتا چلا جائے گا.ایک اور آدمی ان عیوب میں مبتلا ہو تا ہے جو نرمی سے پیدا ہوتے ہیں کوئی ان عیوب میں مبتلا ہوتا ہے جو سختی سے پیدا ہوتے ہیں.اب دیکھو یہ دونوں فطرتیں ہیںاوردونوں مختلف مواقع پر مختلف کام کرتی ہیں.طاقت والا آدمی طاقت کے کام پر تو لگ جائے گا مگر جہاں دبنے کامعاملہ آئے وہاں وہ دب نہیں سکے گا اور نرم طبیعت آدمی نرمی کے کام تو کرے گا مگر مقابلہ اور طاقت والا کام نہیں کرسکے گا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کو خوب سمجھتے تھے.اور آپ ہر شخص کی فطرت کے مطابق کام لیا کرتے تھے.صلح حدیبیہ کے موقع پر عرب کا ایک سردار آیا جس پر قربانیوں کا بہت اثر ہو تا تھا.آپ کو اس کی آمد کاعلم ہوا تو آپ نے فرمایا ساری قربانیاں اس کے راستہ میں کھڑی کر دو.جب تمام قربانیاں اس کے سامنے کھڑی کی گئیں تو اس نے حیران ہو کر پو چھا کہ یہ جانور کیسے ہیں ؟ صحابہ ؓ نے جواب دیا کہ یہ قربانیاں ہیں اس بات کا اس سردار پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے واپس جا کر اپنی قوم سے کہا کہ انہیں مکہ میں آنے کی اجازت دینی چاہیے.ایسا نہ ہو کہ ان کی قربانیاں ضائع چلی جائیں.یوں وہ لڑاکا تھا مگر قربانیوں کو دیکھ کر اس کا دل برداشت نہ کر سکا کہ خدا کے نام کی قربانی رائیگاں چلی جائے.اس بارہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیںکہ اگر کوئی شخص تجھےیہ کہے کہ احد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو تُو اس کی بات مان لے لیکن اگر کوئی شخص تجھے یہ کہے کہ کسی کی فطرت بدل گئی ہے توتُو اس کی بات نہ مانیو.اور یہ بات صحیح ہے.بعض چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جو فطرت کے مطابق ہو تی ہیں اور بعض چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں جو فطرت کے خلاف ہو تی ہیں.اپنے ارد گرد رہنے والوں کو ہی دیکھ لو بعض لوگ چندے خوب دیں گے لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو کھسک جائیں گے.بعض اور لوگ تمہیں اس قسم کے نظر آئیں گے جو نمازیں بر وقت ادا کر لیں گے لیکن جیب سے پیسہ نکالنے کا وقت آئے تو رونے لگ جائیں گے.پھر ایک اور آدمی اس قسم کا ہوتا ہے کہ اگر اس سے چندہ مانگو تو وہ اپنا گھر بار لٹانے کے لئے تیار ہو جائے گا.وطن سے بے وطن ہو نے پرآمادہ ہو جائے گا.لیکن اگر اسے لڑائی میں جان دینے کے لئے کہو تو گھبرائے گا.حسان بن ثابت ؓ اور ابوھریرۃؓدونوں ایسے تھے جو کسی لڑائی میں شامل نہیں ہوئے.غزوہ احزاب کے موقع پر ایک یہودی جاسوس عورتوںکی طرف آگیا.حسان بن ثابتؓ اس وقت پہرہ پر مقرر تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت صفیہ ؓ نے کہا حسان اسے مار ڈالو یہ جاسوس معلوم ہوتا ہے.حسان کہنے لگے تم مارنا چا ہو تو مار دو مجھ سے تو مارا نہیں جاسکتا.
Page 545
حضرت صفیہ ؓ نے ڈنڈا اٹھا یا اور اس کے سر پر مارا، ڈنڈا لگتے ہی وہ زمین پر گرگیا اور بے ہوش ہو گیا مگر گرتے وقت کپڑا ادھر ادھر ہوجانے کی وجہ سے وہ ننگا ہو گیا.انہوں نے شرم کے مارے اپنا منہ ایک طرف کر لیا اور حسان سے کہا اب تو یہ بےہوش پڑا ہے اگر پہلے نہیں مارا تو اب ہی ماردو.حسان ؓ کہنے لگے نہ بی بی ابھی اس کے اندر جان معلوم ہوتی ہے.ایسا نہ ہو کہ مجھ پر حملہ کر دے تم خود ہی مارو.چنانچہ حضرت صفیہ ؓ نے منہ پر کپڑا ڈال لیا اور لٹھ مار کر اسے مار دیا (البدایۃ والنـھایۃ سنۃ ۵ ھـ غزوۃ خندق).اب یہ تو نہیں کہ حضرت حسان ؓ نعوذ باللہ بے ایمان تھے، وہ بڑے مخلص صحابی تھے مگر لڑائی ان کی طبیعت کے خلاف تھی.تو جو چیزیں طبیعت کے مطابق ہو تی ہیں ان کا کرنا بڑا آسان ہو تا ہے اور جو چیزیں طبیعت یامزاج کے خلاف ہو تی ہیں ان کا کرنا بڑا مشکل ہو تا ہے.ایسی کمزوریوں کا علاج بھی صرف اور صرف عادت ہے.مثلاً اگر سو نیکیاں ہیں جن کا بجا لانا ضروری ہے اور سو بدیاں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے اور ان میں سے پچاس نیکیاں اور پچاس بدیاں کسی کی طبیعت کے مطابق ہیں تو پچاس نیکیاں اور پچاس بدیاں ایسی ہوں گی جو طبیعت کے مطابق نہ ہو نے کے سبب سے بہت زیادہ جدو جہد کی محتاج ہو ں گی.اور یہ ظاہر بات ہے کہ جب تک طبیعت جیسی کوئی طاقتور چیز مدد نہ کرے تب تک انسان بدیوں سے رک نہیں سکتا.بہر حال کوئی حربہ ایسا چاہیے تھا جو طبیعت کے برابر وزن رکھتا جس سے اس موقع پر مدد لی جاتی اور وہ حربہ عادت کا ہے.جب انسان اس حربہ کو اختیار کر لیتا ہے تو ان نیکیوں کا حصول اور بدیوں سے اجتناب بھی اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے.جو اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتیں.لوگوں میں یہ بحث چلی آتی ہے کہ طبیعت کا اثر قوی ہوتا ہے یا عادت کا اور اس بارہ میں بعض عجیب عجیب قصے مشہور ہیں.کہتے ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اس کی بیوی میں ایک دفعہ اس پر جھگڑا شروع ہو گیا کہ تخم تاثیر یا صحبت کا اثر ان دونوں میں سے زیادہ طاقت کس میں ہے.تخم تاثیر سے مراد طبیعت ہے اور صحبت کے اثر سے مراد عادت ہے.بیوی کہتی کہ طبیعت کا اثر زیادہ ہو تا ہے اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کہتے کہ صحبت اور عادت کا اثر زیادہ ہوتا ہے.آخر اس کے فیصلہ کے لئے انہوں نے ایک لڑکا پالا وہ میراثیو ں کا لڑکا تھا.سات آٹھ سال تک اسے سکول میں تعلیم دلائی گئی اور اس کے ماحول کو بالکل بدل دیا گیا.ایک دن انہوں نے یہ معلوم کرنا چا ہا کہ طبعی میلان قوی ہے یا عادت.چنانچہ انہوں نے اس دن برتن میں روٹی رکھنے کی بجائے ایک ٹوٹی پھوٹی جو تی لپیٹ کر رکھ دی.لڑکا سکول سے واپس آیا اور ر وٹی کھانے کے لئے اس نے برتن پر سے کپڑا اٹھایا تو بجائے روٹی کے اس میں سے جوتی نکل آئی یہ دیکھ کر وہ بےتحاشا رونے لگ گیا.مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بیوی سے کہا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ صحبت کا اثر زیادہ ہو تا ہے
Page 546
چونکہ یہ شریفوں میں پلا ہے اس لئے اسے دکھ ہوا ہے کہ میرے ساتھ ایسا گندہ مذاق کیوں کیا گیا ہے.بیوی نے کہا اس سے بھی تو پوچھ دیکھو کہ یہ کیوںرورہا ہے انہوں نے لڑکے سے پوچھا کہ تو کیوں رو تا ہے تو اس نے جواب میں کہا کہ آپ تو دو دو کھائی ہیں اور میرے لئے ایک ہی رکھی ہے.بیوی کہنے لگی دیکھا تخم تاثیر کتنی طاقت رکھتا ہے کہ اتنے لمبے عرصہ کے بعدبھی اس میراثی کی طبیعت نہیں بدلی.حقیقت یہ ہے کہ طبعی امور اپنے اندر بڑی طاقت رکھتے ہیں لیکن طبیعت کو کسی بات سے ہٹانے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ عادت ہے اگرعادت کا حربہ نہ ہو تا تو انسان کہتا میری طبیعت میں نرمی ہے اس لئے میں سختی والے کام نہیں کر سکتا یا میری طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے اس لئے میں نرمی سے کام نہیں لے سکتا.حضرت عمر ؓ وہ شخص تھے جو بات بات پر تلوار نکال لیا کرتے تھے.بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آپ فلاں شخص کے متعلق اگر ذرا بھی اشارہ کر دیتے تو میں اسے قتل کر دیتا.مگر پھر یہی عمر ؓ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنتے سنتے اتنے نرم دل ہو گئے کہ صحابہؓ کہتے ہیں اپنی خلافت کے زمانہ میں ہم نے عمرؓ سے زیادہ با ت بات پر رونے والا اور کوئی شخص نہیں دیکھا.طبیعت وہی تھی لیکن عادت کے ساتھ حضرت عمرؓ نے اس کو دبا لیا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مانتے ہیں کہ ماں باپ کے اثر، گندے ماحول اور خراب تعلیم سے کئی قسم کی خرابیاں پید اہو جاتی ہیں.لیکن اس کے مقابلہ میں ہم نے عادت کی خوبی بھی رکھی ہے جس چیز کی تم عادت ڈال لو وہی چیز تمہارے لئے آسان ہو جائے گی فطرت انسانی کڑواہٹ کو نا پسند کرتی ہے، شراب کڑوی ہو تی ہے لیکن پندرہ بیس دن شراب پینے کے بعد ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کی کڑواہٹ ذرا بھی بری محسوس نہیں ہو تی اور لوگ اس کے پینے میں لذت محسوس کرتے ہیں.غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ بدیاں مٹانے کے لئے ہم نے عادت کا حربہ پیدا کیا ہوا ہے.جو چیزیں تمہاری فطرت کےمطابق ہیں وہ تو ہیں ہی، جو خلاف ہیں ان کی عادت ڈال لو.ایک ایک بدی لے کر اس سے بچنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لو نتیجہ یہ ہو گا کہ عادت غالب آ جائی گی.پھر دوسری بدی کو پکڑ لو وہ دور ہو جائے تو تیسری بدی کو پکڑلو.اس طرح رفتہ رفتہ تمام بدیاں دور ہو جائیں گی.اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر رمضان میں کسی ایک بدی کو دور کرنے کا تم عہد کر لو.اور جہاں تم خدا کے لئے کھانا پینا چھوڑتے ہو وہاں ایک بدی بھی چھوڑ دو.دوسرا رمضان آئے تو دوسری بدی چھوڑنے کا عہد کر لو.اس طرح چند رمضان کے مہینوں میں کئی بدیاں چھٹ جائیں گی یہ بھی دراصل عادت ڈالنے والی ہی بات ہے جب انسان عہد کرے گا کہ اس مہینہ میں مَیں نے فلاں کام نہیں کرنا تو اس کے نہ کرنے کی عادت
Page 547
ہوجائے گی اور رفتہ رفتہ وہ بدی بالکل چھٹ جائے گی.بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ عادت کی نیکی کوئی نیکی نہیں وہ بھی کوئی نیکی ہے جس کی عادت پڑ جائے.لیکن یہ غلط بات ہے.عادت کی نیکی بعض دفعہ توبے شک نیکی نہیں ہو تی لیکن بعض دفعہ ہو تی ہے.در اصل یہ دو الگ الگ مواقع ہیں جن کی وجہ سے عادت کی نیکی بعض دفعہ نیکی بن جاتی ہے اور بعض دفعہ نیکی نہیں رہتی.جب انسان کو اپنی سمجھ بوجھ کے زمانہ سے پہلے کسی چیز کی عادت پڑے اور پھر اسے اس عادت پر غور کرنے اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کا کبھی موقع نہ ملا ہو تو وہ نیکی نیکی نہیں کہلاتی مثلاً اگر کسی شخص کو بچپن سے سچ بونے کی عادت ہے یا نماز پڑھنے کی عادت ہےاور بعد میں اسے سچائی اور نماز پر غور کرنےکا موقع نہیں ملا اور وہ ان نیکیوں کو علیٰ وجہ البصیرت نہیں بلکہ محض عادت کی وجہ سے بجا لاتا ہے تو اس کی یہ نیکیاں محض عادتی نیکیاں قرار پائیں گی.لیکن جو شخص کسی بات کو سمجھتے ہوئے اس کی عادت ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اندر نیکی کو قائم کروںاور بدی سے بچوں تو وہ اس کی محنت کا ثمرہ اور پھل ہے اور اچھا کام کرنے پر انعام تو ملا ہی کرتا ہے مثلاً جو انسان ابتدا سے جھوٹ بولنے کا عادی ہے اور جس کی گھٹی میں جھوٹ بولنا داخل ہے وہ جب کوشش کرے گا کہ میں آئندہ سچ بولوں تو یہ لازمی بات ہے کہ اسے تکلیف ہو گی لیکن جب پندرہ بیس دفعہ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال کر وہ سچ بو لے گا تو اس کے بعد سچ بولنے کی عادت اس میں پیدا ہو جائے گی.اور وہ نتیجہ ہو گا اس کی محنت کا اور جو پھل کسی کی محنت اور کوشش کا ہو اس سے وہ محروم نہیں کیا جاسکتا.پس جس بدی کا ترک انسان نے محنت سے کیا ہواور جس نیکی کے بار بار اور بالارادہ کرنے کی وجہ سے انسان کو اس کی عادت ہوگئی ہو وہ نیکی ایک قابل قدر نیکی ہے.پس یہ غلط بات ہے کہ عادت کی نیکی نیکی نہیں ہوتی.جب یہ عادت زور سے پیدا کی جائے گی اور اس کے لئے محنت اور کوشش کی جائے گی تو اس کا جو نتیجہ پیدا ہو گا اس سے وہ محروم نہیں کیا جا سکتا.اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئےسو جاتا ہے اس کی ساری رات ہی عبادت اور دعا میں بسر ہو تی ہے.در اصل ہر انسان کے اندر ایک نفس مکتوم یعنی SUBJECTIVE MINDہوتا ہے جو دماغ کے خزانہ کے طور پر کام کرتا ہے جب انسان دعا کرتے ہوئے سوتا ہے تو گو بظاہر وہ سویا ہوا ہوتا ہے مگر اس کا نفس مکتوم کا م کر رہا ہو تا ہے یہ دعا اس کے ارادہ کے ماتحت نہیں ہو تی او ربظاہر ا س کا ثواب اسے نہیں ملنا چاہیے لیکن چونکہ یہ اس کی جاگنے والی دعا کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کا ثواب اسے ضرور ملے گااور ملتا ہے.دین کے دسویں معنے قضاء کے (۱۰)دین کے دسویں معنے قضاء کے ہیں.اس لحاظ سے اَرَءَیْتَ الَّذِیْ
Page 548
یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ کے یہ معنے ہوں گے مجھے بتا تو سہی اس شخص کا حال جو قضاء کا انکار کرتا ہے.(یہی جو انکا رکرتا ہے)تو ا سے دیکھے گاکہ وہ یتیم کو دھتکار تا ہے (یَدُعُّ الْیَتِیْمَ ) سیاق و سباق سورۃ کے لحاظ سے قضاء کے معنے اس جگہ قضائے الٰہی کے ہیں یعنی کون ہے وہ شخص جو قضائے الٰہی کا انکار کرتا ہے.مگر قضائے الٰہی سے مراد وہ قضائے الٰہی نہیں جس کا آج کل مسلمانوں میں خیال پایا جاتا ہے یا جس کا دوسرے مذاہب میں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مجبور پیدا کیا ہے.اسے مومن یا کافر، عالم یا جاہل، اندھایا آنکھوں والا، کمزور یا طاقتور خود بنا دیا ہے.اور وہ اپنی حالت کو بدل نہیں سکتا.اگر یہاں وہی قضاء مراد لی جائے جس کا آج کل مسلمانوں میں عقیدہ پایا جاتا ہے یا جو دوسرے مذاہب میں اس سے مراد لی جاتی ہے تو اس آیت کے کوئی معنے نہیں رہتے.جب انسان پیدا ہی مجبور کیا گیا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون پر چل رہا ہے.اور ا سے توڑ نہیں سکتا.تو اس آیت کے معنے ہی کیا ہوئے کہ مجھے بتا تو سہی وہ شخص جو خدا تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے کیسا مجرم ہے یہ معنے بالکل بےجوڑ ہوجاتے ہیں در حقیقت یہاں قضاءِ الٰہی سے مراد وہ قضاءِ الٰہی ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے.چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ (الذّٰاریٰت :۵۷) کہ میں نے جنّ و انس کو ایک خاص مقصد کے لئے پید اکیا ہے.اور وہ مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں.اب لِیَعْبُدُوْنِ سے ظاہری عبادتیں تو مراد نہیں بلکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ وہ ایسے بن جائیں کہ حقیقی طور پر خدا تعالیٰ ان کے دل میں آجائے.اگر لِیَعْبُدُوْنِ سےظاہری عبادتیں مراد ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ الَّذِیْنَ ھُمْ عَنْ صَلَاتِھِمْ سَاھُوْنَ کہ لعنت ہے ان نماز پڑھنے والوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہیں.ا س سے معلوم ہو تا ہے کہ بعض نمازیں ایسی بھی ہو تی ہیں جو پڑھنے والے کے لئے لعنت کا موجب ہوتی ہیںاور بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لئے رحمت کا موجب ہو تی ہیں پس آیت مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ میں لِیَعْبُدُوْنِ سےمراد ظاہری عبادات نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات انسان کے اندر جاگزیں ہو جائیں اور وہ خدا تعالیٰ کا صحیح مظہر اورنمونہ بن جائے یہی مقصد تھا جس کے لئے خدا تعالیٰ نے جنّ و انس کو پیدا کیا اور یہی ایک تقدیر الٰہی ہے اور اسی کی طرف مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ کی آیت میں اشارہ ہے یعنی ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ محض اسی لئے پیدا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بن جائے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے اور یہ قانون حصر کے طور پر بیان ہوا ہے.کیونکہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی جملے میں مَا اور اِلّا آجائیں تو وہ حصر کے معنے دیتا ہے پس مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ کے معنےعربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے یہی بنتے ہیں
Page 549
کہ یہی وہ مقصد ہے جس کے لئے جنّ و انس کو پید اکیا گیا ہے.اس کے سوا ان کی پیدائش کا اور کوئی مقصد نہیں.یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِیَعْبُدُوْنِ سےمراد یہ نہیں ہوسکتا کہ میں نے جنّ و انس کو اس لئے پیدا کیا ہے تا وہ میری مخلوق بن جائیں کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تو وہ اسی وقت مخلوق ہو گئے دوبارہ مخلوق بننے کا سوال ہی نہیں رہتا.پس اس آیت کے یہی معنے ہیں کہ انسان کواس لئے پید اکیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح عبد بن جائے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کوجذب کرلے اور اس کا سچا، مخلص اور مومن بندہ بن جائے یہی قضائے الٰہی ہے.اور اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جو مذکورہ بالا قضائے الٰہی کا انکار کرے وہ کبھی نیک نہیں ہو سکتا اور اس کے افعال ضرور گندے ہوںگے.پس جو شخص قضائے الٰہی کو سمجھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے کہ وہ صرف اس لئے پیدا کیا گیا ہے تا خدا تعالیٰ کا مخلص اور مومن بندہ بن جائے اور ا سے اس بات پر یقین ہو تو وہ خود اپنی اصلاح کر لے گا.کیونکہ وہ سمجھ لے گا کہ میں یقیناً بدیوں پر غالب آسکتا ہوں کیونکہ میری پیدائش کی غرض ہی نیک ہونا ہے.گناہ درحقیقت بڑھتا ہی مایوسی سے ہے جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں ان میں مقابلہ کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور وہ شیطان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیںدنیا میں ہزاروں ہزار لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کوئی رستہ تجویز نہیں کیا.اور ا س لئے وہ مایوس ہوجاتےہیں.ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے ہماری نجات کا کوئی رستہ تجویز ہی نہیں کیاتو پھر بدی کا مقابلہ کرنے سے کیا فائدہ.ایسے لوگ اپنی بدیوں کی وجہ سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ان کے لئے کوئی راہ نجات نہیں.اس لئے ان کےاندر نیکی کے لئے خاص جدو جہد پیدا نہیں ہو تی.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے وَ لَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (السجدۃ:۲۸) یعنی اگر ہم اپنی مرضی سے کام لیں تو ہر شخص کو ہدایت دے دیں.یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کو استعمال کرے گا اس کی مشیت یہی ہو گی کہ سب جِنّ و انس اس کے مخلص اور مومن بندے بن جائیں اور وہ ہدایت پا جائیں.اس کی مشیت یہ نہیں ہو گی کہ وہ گمراہ ہو جائیں اور ہدایت سے ہٹ جائیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ چور اور ڈاکو بن جائے بلکہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کا عبد بن جائے اس کا بندہ بن جائے.اس بات کی تردید کہ ہر ایک روح جہنم میں جائے گی لیکن خدا تعالیٰ ساتھ ہی یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے ایک اور قانون بھی مقرر کر دیا ہے اور وہ بھی نظر انداز نہیں ہو سکتا او
Page 550
الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ میں تما م جنّوں اور انسانوں کو جہنم میں داخل کروں گا اس آیت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے یہ قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام جنّ و انس جہنم میں جائیں گے.حالانکہ دوسری آیات سے پتہ چلتا ہےکہ ان کا یہ خیال غلط ہے اللہ تعالیٰ سورۂ رحمٰن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہٖ جَنَّتٰنِ(الرَّحْـمٰن:۴۷).جو شخص اپنے اندر خوف پیدا کر لیتا ہے اسے دو جنتیں ملیں گی.اس جہان میں بھی اسے جنت ملے گی اور اگلے جہان میں بھی اسےجنت ملے گی اب جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کے لئے اس جہان میں بھی جنت ہے اور اگلے جہان میں بھی جنت ہے اسے دوزخ کہاں ملے گی.دو ہی زمانےہیں.یہ جہان ہے یا اگلا جہان ہے.اسے یہاں بھی جنت مل گئی اور اگلے جہان میں بھی جنت ملے گی تو دوزخ کہاں ملی.پس معلوم ہوا کہ یہ گروہ جس کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے دوزخ میں نہیں جائے گا اور اگر یہ گروہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ کےجو یہ معنے کئے جاتے ہیں کہ میں جنّ و انس میں سے ہر ایک کو جہنم میں ڈالوں گا کیسے صحیح ہو سکتے ہیں.معلوم ہوا کہ یہ معنے ٹھیک نہیں.اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُ.ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.(الفجر:۲۸تا۳۱)کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہےاور وہ تجھ سے راضی ہے.اس آیت میں لفظ اِرْجِعِيْ یا تو اس جہان کے متعلق ہے یا موت سے بعد کی زندگی کے متعلق ہے.ان دونوں کے علاوہ اس کے کوئی اور معنے نہیں لئے جا سکتے جب خدا تعالیٰ کسی شخص سے راضی ہو گیا ہو اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گیا ہوتو پھر وہ دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟اور اگر اس سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے تب بھی یہ آیت بتاتی ہے کہ مرنے کےبعد فوراً اسے کہا جائے گا فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَ ادْخُلِيْ جَنَّتِيْ.جاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر دوزخ میں جانے کا کون سا وقت آئے گا معلوم ہوا کہ یہ بات غلط ہے کہ ہر ایک روح جہنم میں جائے گی.ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَا ذَاۤ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ١ؕ قَالُوْا خَيْرًا١ؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ١ؕ وَ لَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ١ؕ وَ لَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ.جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا۠ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ١ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ.الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ طَيِّبِيْنَ١ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ١ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.(النحل :۳۱تا۳۳)یعنی متقیوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے یعنی وہ کیا پُر حکمت کلام ہے اس پر وہ کہیں گے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا ہے ٹھیک
Page 551
ہے.یعنی اس نے کوئی بھی ایسا حکم نازل نہیں کیا جو ہمارے لئے مضرّت رساں ہو.ہر حکم جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ہمارے لئے مفید اور بابرکت ہے اور ہماری ترقیات کے لئے ہے پس جب خدا تعالیٰ کا کلام خیر ہی خیر ہے جب خدا تعالیٰ کا کلام خوبی ہی خوبی ہے.جب خدا تعالیٰ کا کلام نیکی ہی نیکی ہے تو لازمی بات ہے کہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے لئے ورلی دنیا میں بھی بھلائی ہو گی اور اگلے جہان میں بھی بھلائی ہو گی اور ان کو ہمیشہ رہنے والے باغات ملیں گے جن میں ہر خواہش پوری ہو گی.اللہ تعالیٰ متقیوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے.ملائکہ ان کی روح اس حالت میں نکالیں گے کہ وہ مومن بالکل پاک صاف ہوں گے تب ملائکہ ان سے کہیں گے کہ تم پر ایک عظیم الشان سلامتی کا نزول ہو نے والا ہے.جاؤ اور جا کر جنت ِ الٰہی میں داخل ہو جاؤ.یعنی جنت میں داخلہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا وصال جو سب سلامتیوں کا سردار ہے تم کو حاصل ہو گا.پس جس مومن کے لئے اس جہان میں بھی جنت ہے اور اگلے جہان میںبھی اسے جنت ملے گی اس کے دوزخ میں جانے کا امکان ہی نہیں.مذکورہ بالا آیت میں جو الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ طَيِّبِيْنَ فرمایا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہاں متقیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی کی صورت میں مریں.متقی سے یہ مراد نہیں کہ وہ بچپن سے آخر عمر تک نیکی ہی نیکی کرے.بلکہ موت سے پہلے جس کی حالت کامل اور نیک ہو جائے گی وہ متقی ہے اگر اس سے پہلے کوئی گناہ اس نے کیا ہے تو وہ معاف کر دیا جائے گا.حدیث شفاعت بھی اس امر کی وضاحت کرتی ہے کہ کامل مومن کے لئےدوزخ نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے اسّی۸۰ ہزارآدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یعنی سوال و جواب سے جو کوفت ہوتی ہے وہ بھی انہیں نہیں ہوگی وہ بغیر سوال و جواب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے ظاہر ہے کہ ان سے بھی زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو سوال و جواب کے بعد جنت میں جائیں گے.پس لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ کے یہ معنے کرنا کہ ہر جنّ و انس دوزخ میں سے ہو کر جائے گا بالکل لغو ہیں.مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ دوزخ مومن کے لئے جنت بن جائے گی.وہاں باغات ہوں گے پھول ہوں گے.لیکن اوّل تو یہ ایک تمسخر بن جاتا ہے کہ انبیاء ، صلحاء کو دوزخ میں ڈالا جائے لیکن بنا دیا جائے اسے جنت دوسرے اس طرح مومنوں کو یہ کوفت تو ہوگی کہ خدا تعالیٰ ان سے ناراض ہے اس لئے وہ انہیں دوزخ میں بھیج رہا ہے.بعد میں بے شک انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ دوزخ نہیں ہے جنت ہے.یہاں تو باغات ہیں پھول کھلے ہیں آخر یہ عذاب انہیںکس قصور کی بنا پر دیا جائے گا؟ اور پھر یہ خیال کر لینا کہ نعوذباللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام
Page 552
اور حضرت نوح علیہ السلام بھی ایک وقت دوزخ میں جائیں گے کس طرح درست ہو سکتا ہے ؟ حقیقت یہ ہےکہ ان آیات نے صاف طور پر ثابت کر دیا ہے کہ بہت سے مومن ایسے ہوں گے ( اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی کروڑوں ہو گی یااربوں ہو گی ) جو سیدھے جنت میں جائیں گے اور دوزخ ا ن کے پاس بھی نہیں پھٹکے گی.اگر یہ ٹھیک ہے تو لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ کے کیا معنے ہوں گے ؟سو اس کے ایک معنے تو یہ ہو سکتے ہیں کہ الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ دونوں میںالف لام عہد کا ہے.الف لام کے کئی معنے ہوتے ہیں الف لام جنس کے لئے بھی آتا ہے یعنی کسی جنس کے جتنے افراد ہو تے ہیںوہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں.اسی طرح معہود ذہنی یا ذکری کے لئے بھی آتا ہے یعنی جس جماعت کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہو اس کی طرف اس میںاشارہ ہو تا ہے مثلاً ہم کہتے ہیں جَاءَالرِّجَالُ.لوگ آگئے.یہاں الف لام جنس کے لئے نہیں اس کے یہ معنے نہیں ہیں کہ دنیا کے سب لوگ آگئے.بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے آنے کی ہم امید کرتے ہیں یا جن کا پہلے ذکر کیا گیا.پس الْجِنَّۃِ وَالنَّاسِ سےمراد یہاں یہ ہوںگے کہ وہ جنّ و انس جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے سب دوزخ میں جائیں گے اور پہلے ذکر کفار کا ہے مومنوں کا نہیں.پس مطلب یہ ہوا کہ کفار میں سے بڑےلوگ اور عوام الناس سب جہنم میں جائیں گے کیونکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہیں.خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جائے گی.دوسرے معنے اس آیت کے یہ ہو سکتے ہیں کہ جنت کے لئے بھی دوزخ میں سے ہو کر رستہ ملتا ہے.اس دوزخ سے مراد خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی دوزخ نہیں بلکہ محض تکالیف مراد ہیں.حقیقت یہ ہے کہ دوزخ دو قسم کی ہو تی ہے ایک خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی دوزخ.دوم وہ دوزخ جو انسان خود اپنے نفس کو کچلنے کے لئے دنیا میں تیار کرتا ہے.یعنی ایک دوزخ انسان خود بناتا ہے اور ایک دوزخ خدا تعالیٰ بناتا ہے.جو دوزخ خدا تعالیٰ بناتا ہے وہ اس کی ناراضگی پر دلالت کرتی ہے اور جو دوزخ انسان خود اپنے نفس کو کچلنے کے لئے تیار کرتا ہے ( اگرچہ وہ ظاہر میں دوزخ معلوم ہو تی ہے لیکن اصل میں وہ جنت ہو تی ہے )وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی پر دلالت نہیں کرتی بلکہ انسان خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے خود اپنے اوپر اسے وارد کرلیتا ہے.مثلاً ایک انسان رات کو اٹھتا ہے، اپنے آرام کو خراب کرتا ہے، دوسرے لوگ سو رہے ہو تے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہو تے ہیں ،بستروں میں آرام کر رہے ہو تے ہیں لیکن یہ اٹھتا ہے، اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتا، نیند کو خراب کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے.یا لوگ روپیہ جمع کرتے ہیں مگر یہ اپنے مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں لٹاتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کی راہ میں اسے خرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے یا یہ روزے رکھتا ہے، دوسرے لوگ عیش کی زندگی گذارتے
Page 553
ہیں، مچھلی کے کباب اڑاتے ہیں، مرغے اڑاتے ہیں، برف والا پانی پیتے ہیں.لیکن یہ اپنے اوپر پانی بھی حرام کر لیتا ہے اور سارا دن کچھ نہیں کھاتا.یہ دوزخ ہے یا نہیں.خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ کہ ہر ایک جنّ و انس کو جہنم میں سے ہو کر جانا پڑےگا ایک طرف واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ مومن کامل سیدھا جنت میں جائے گا.اور دوسری طرف یہ فرمایا گیا ہے کہ جنت بغیر کانٹوں میں سے گذرے نہیں ملے گی.پس ثابت ہوا کہ ہر انسان کو دوزخ میں سے ہو کر گذرنا پڑے گا خواہ وہ دوزخ انسان اصلاح نفس کے لئے خود تیار کرے یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، قربانیاں کرے، اپنی زبان کو روکے اور اپنے نفس کو شہوات سے روکے اور خواہ اس دوزخ میں سے گذرنے کے لئے تیار ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی دوزخ ہے.اوّل الذکر دوزخ میں سے سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے انبیاء گذرے ہیں.خدا تعالیٰ کے انبیاء سے زیادہ دنیا میں خدا تعالیٰ کی خاطر کون تکلیف اٹھاتا ہے.اپنے لئے سب سے بڑا دوزخ انبیاء ہی تیار کرتے ہیں.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا زیادہ کسی کو خدا تعالیٰ سے پیار ہو گا اتنی ہی زیادہ وہ دنیا میں تکلیفیں اٹھائے گا پس لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ میں یا تو اس آیت کے سباق کی طرف اشارہ ہے جس میںکفار کا ذکر ہے اور یا دوزخ سے مراد یہاں صرف خدا تعالیٰ کی ناراضگی والی دوزخ نہیں بلکہ وہ تکلیف و دکھ کی دوزخ بھی مراد ہے جس میں سے مومن خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے اپنی مرضی سے گذرتا ہے.دوسری بعض آیات جو اس مضمون کو واضح کرتی ہیں کہ ہر جنّ و انس دوزخ میں سے ہو کر نہیں جائے گا یہ ہیں وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۤ١ٞ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ١ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ١ۚ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا١۫ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ١ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ١ؕ وَ نُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا١ؕ قَالُوْا نَعَمْ١ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا١ۚ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ كٰفِرُوْنَ.وَ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ١ۚ وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّۢا بِسِيْمٰىهُمْ١ۚ وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ١۫ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَ.وَ اِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ اَصْحٰبِ النَّارِ١ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰىهُمْ قَالُوْا مَاۤ اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَ مَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ۠.اَهٰۤؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا
Page 554
يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ١ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ.(الاعراف: ۴۳تا۵۰) ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے مناسب حال اعمال کئے ان پر ہم وہ بوجھ نہیں ڈالیں گے جن کے اٹھانے کی ان میں طاقت نہ ہو.وہ لوگ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے.دیکھو یہ کیسا لطیف مضمون ہے اس خوف سے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جنت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پیدائش کے وقت سے لے کر آخر وقت تک یعنی موت تک اس نے کوئی ٹھوکر نہ کھائی ہو اور اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بھی زور لگاکر اپنی اصلاح کر تا ہے اور نیک کام کرتا ہے خواہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے پہلے ہی فوت ہو جائے.ہم اس کے گناہ معاف کر دیں گے اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا.پھر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ١ۚ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰىنَا لِهٰذَا١۫ وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَاۤ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ١ۚ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ١ؕ وَ نُوْدُوْۤا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.کہ ہم ہر قسم کا کینہ ان کے دلوں سے نکال دیں گے ان کے نیچے نہریںبہتی ہو ں گی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے جس نے انہیں جنت کا رستہ دکھایا اگر اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا رستہ نہ دکھاتا تو وہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے اور یہ قضاء الٰہی تھی جو اس طرح ظاہر ہوئی کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے.اگر وہ رسول ان کے پاس نہ آتے تو وہ اس ہدایت کو نہیں پا سکتے تھے اور انہیں پکار پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تم نے دنیا میں نیک اعمال کئے ہیں اس لئے تم جنت کے وارث قرار دیئے گئے ہو.پھر فرمایا وَ نَادٰۤى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا١ؕ قَالُوْا نَعَمْ١ۚ فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌۢ بَيْنَهُمْ اَنْ لَّعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.جنت والے دوزخ والو ں سے کہیں گے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا.کیا تم سے جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے ؟ وہ کہیں گے ہاں وہ وعدہ بھی پورا ہو گیاہے اور پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے.اب دیکھو اگر یہ لوگ دوزخ میں سے ہو کر جنت میں جاتے تو انہیں آواز دے کر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی.جب وہ اکٹھے دوزخ میں آئے تو یہ پوچھنے کے کیا معنے ہو سکتے ہیں کہ تم سے جو وعدہ خدا تعالیٰ نے کیا تھا آیا وہ پورا ہو گیاہے یا نہیں.وہ تو انہیں دوزخ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے.جنت والوں کا آواز دینا صاف بتاتا ہے کہ وہ دوزخ میں نہیں گئے.کیا ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی یا آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں دوزخ میں سے گذارا جائے گا کہ انہیں ایک دوسرے کو آواز دے کر پو چھنے کی ضرورت ہو گی.پھر فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ کہ مومنوں اورکافروں کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا تا دوزخیوں کو دیکھ کر مومنوں کے
Page 555
دل گھبرا نہ جائیں خدا تعالیٰ تو مومن کے دل کا اتنا لحاظ کرتا ہے کہ فرماتا ہے مومنوں کو دوزخ کا عذاب دور سے دیکھنے کی تکلیف سے بھی بچایا جائے گا مگر آج کل کا مسلمان کہتا ہے کہ ہر انسان دوزخ میں ڈالا جائے گا.پھر فرمایا وَ عَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّۢا بِسِيْمٰىهُمْ١ۚ وَ نَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ١۫ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَ هُمْ يَطْمَعُوْنَ یعنی اعراف والے لوگ سب کوان کی شکلوں سے پہچان لیں گے اور جنت والوں کو پکار کرکہیں گے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے بلکہ جنت میں داخل ہو نے کی امید کرر ہے ہوں گے.ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ گروہ بھی دوزخ سے باہر ہو گا اور اعراف والے ان سے یہ کہیں گے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو.سابق مفسرین نے اس آیت کے معنے کرنے میں غلطی کھائی ہے اور کہا ہے کہ اعراف والےلوگ وہ ہیں جن کی جنت کا فیصلہ نہیں ہوا ہو گا(تفسیر الخازن سورۃ الاعراف زیر آیت الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ يَبْغُوْنَهَا عِوَجًا....).حالانکہ اعراف والے لوگوں کی نسبت تویہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے لوگوں سے مخاطب ہوکر سوال و جواب کریں گے اور یہ مقام اعلیٰ لوگوں کا ہو تا ہے پس اعراف والے ادنیٰ درجہ کے مومن نہیں بلکہ انبیاء و صلحاء کامل کا گروہ ہے یہ گروہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ گھبراؤ نہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہے.اس لئے کہ یہ عام مومن ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہو ں گے بلکہ جنت میں داخل ہو نے کی امید کر رہے ہو ں گے اور خوف سے گھبرائے ہوئے ہو ں گے.اعراف والے ان کو تسلی دیں گے کہ تم پر سلامتی ہی سلامتی ہے گھبراؤ نہیں.پھر اسی اعلیٰ گروہ کی توجہ اہل دوزخ کی طرف پھیری جائے گی تو وہ کہیں گے.اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کیجیو.یہاں پر ایک عجیب لطیفہ ہے.مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب الاعراف سے مراد یہاںادنیٰ درجہ کے لوگ ہیں.اگر یہ معنے بھی مان لئے جائیں تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ادنیٰ درجہ کے لوگ بھی جنت میں جائیں گے.چنانچہ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کیجیو.یہ عجیب بات ہے کہ مفسرین کے نزدیک تو معمولی درجہ کے مومن جنت میں نہیںجائیں گے لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ادنیٰ درجہ کے مومن بھی جنت میں جائیں گے اور دوزخ کی آگ سے بچائے جائیں گے.پھر فرمایا اصحاب اعراف کفار سے کہیں گے کہ تم کو تمہارے جتھوں نے فائدہ نہیں پہنچایا.تم مومنوں کے بدخواہ تھے لیکن دیکھو آج وہ جنت میں جا رہے ہیں اور پھرمومنوں سے کہیں گے کہ جاؤ اب جنت میں داخل ہو جاؤ.ان آیات سے دوباتیں ظاہر ہیں.اوّل مومن دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ مومن دوزخ سے دور کھڑے ہوں گے کہ انہیں اصحاب اعراف جنت میں جانے کا حکم دیں گے.دوسرے یہ کہ اصحاب اعراف کمزور مومنوں کا نام
Page 556
نہیں کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اعراف والے دوسرے مومنوں کو اجازت دیں گے کہ جاؤ جنت میںداخل ہوجاؤ.کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ ادنیٰ درجہ کے لوگ اعلیٰ درجہ والوں کو جنت میں داخل ہو نے کی اجازت دیں گے.اوپر کی آیات سے بھی صاف ثابت ہو تا ہے کہ تقدیر الٰہی یہی ہےکہ ہر ایک انسان کو جنت میں داخل کیاجائے.لیکن اگر کوئی دوزخی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی راستہ سے بھولا بھٹکا مسافر.لیکن کسی نہ کسی دن وہ بھی ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا.اگر ان دوزخیو ں کو قضائے الٰہی پر یقین ہوتا اور وہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے مخلص اور مومن بندے بن جائیں تو وہ ضرور نیکی کے لئے جد و جہد کرتے اور اپنے نفسو ں کی اصلاح کرتے پس جب انسان قضائے الٰہی پر یقین نہیں رکھتا تو وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے اور مختلف قسم کی بدیوں میںمبتلا ہو جاتا ہے.مثلاً عیسائیوں کا قضاء الٰہی پر ایمان ایسا ہی ہے.ان کا عقیدہ ہے کہ انسان گناہ گار پیدا ہو تا ہے اور جب تک وہ کفارہ پر ایمان نہ لائے وہ پاک نہیں ہو سکتا.اسی طرح ہندو ہیں ان کا بھی قضاء الٰہی پر یقین نہیں.ہندو تناسخ کے قائل ہیں.ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان دوزخ کے لئے پیدا ہوا ہے جنت کے لئے پیدا نہیں ہوا.اللہ تعالیٰ نیکی کا انعام دیتا ہے مگر کوئی نہ کوئی گناہ ایسا رکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اسے پھر دنیا میں بھیج دیتا ہے کوئی قسمت والا ہی نیکیاں کر کے جنت میںجاتا ہے.مگر خدا تعالیٰ اسےاس کے کسی قصور کے بدلہ میںجو چھپا کر رکھ لیا جاتا ہے پھر دنیا میں بھیج دیتا ہے اس طرح ایک چکر سا بندھ جاتا ہے(ستیارتھ پرکاش سملاس نواں سوال۲۰ صفحہ ۳۱۶، ۳۱۷) انسان نیک اعمال کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے.خدا تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی قصور باقی رکھ لیتا ہےاور آخر اس قصور کے بدلہ میں وہ پھر اسے دنیا میں بھیج دیتا ہے.یہ بالکل وہی بات ہے جو ہندو مسلمانوں سے کرتے ہیں جب تھوڑا سا قرضہ باقی رہ جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں چودھری جی آپ کا قرضہ صاف ہو گیا ہے اس سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے لیکن وہ تھوڑا ساقرضہ جو باقی رہ گیا تھا بڑھتا چلا جاتا ہے مثلاً دس روپے اگر قرضہ تھا تو اس پر ڈیوڑھا سود لگ کر سال میں قرضہ پندرہ روپے ہو جائے گا پھر پندرہ سے بائیس ہو جائے گا اسی طرح وہ بڑھتا جائے گا اور کچھ عرصہ کے بعد جب وہ چودھری ان سے ملے گا یا وہ خود ہی اس کے گھر جائیں گے تو اس سے کہیں گےچودھری جی آپ کا کچھ قرضہ باقی ہے ہم نے اس وقت غلطی سے کہہ دیا تھا کہ قرضہ صاف ہو گیا ہے در اصل غلطی لگ گئی تھی تھوڑا سا قرضہ باقی رہ گیا تھا جو اب سود پڑتے پڑتے اتنا ہو گیا ہے اور اس طرح پھر ایک چکر شروع ہو جاتا ہے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی انسا ن کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے جیسا وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں.اللہ تعالیٰ بھی ان کے نزدیک سلیٹ صاف نہیں کرتا کوئی نہ کوئی گناہ رکھ لیتا ہے جو بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں واپس دنیا میں بھیج
Page 557
دیتا ہے.لیکن یہ سب ڈھکوسلےاور غلط خیالات ہیں درحقیقت خدا تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ جنت میں پہنچانے کے لئے ہماری مدد بھی کرتا ہے.اگر کوئی شخص اس حقیقت کو سمجھ لے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں جنت کے لئے بے حد شوق پیدا ہو جائے گا اور وہ اس کے لئے بے انتہا کوشش اور جدو جہد کرے گا.وہ اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے اس قابل بنائے گا کہ جنت کا اہل بن جائے.اگر وہ اپنی زندگی میں گناہ بھی کرتا رہا ہے تب بھی وہ مایوس نہیں ہو گا اسے یہ امید ہو گی کہ وہ اب بھی نیک عمل کرے تو جنت کو حاصل کر سکتا ہے.پس قضائے الٰہی پر ایمان اور یقین ہو نے سے انسان کا حوصلہ پست نہیں ہوتابلکہ اس کا حوصلہ بلند ہو تا ہے.اگر انسان کو قرآن کریم کی بتائی ہوئی قضائے الٰہی پر یقین ہو گا تو وہ جنت کو حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرے گا اورجسے اس پر ایمان نہ ہو گا وہ مایوس ہو کر گناہ کے سمندر میں کود پڑے گا اور کہے گا کہ انجام تو خراب ہے ہی کیوں نہ اس دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤں.دین کے گیارھویں معنے تدبیر کے (۱۱)گیارھویں معنے دین کے تدبیر کے ہیں.تدبیر کا منکر بھی مختلف گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے اور نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے.اگر کوئی شخص تدبیر کا منکر ہے.کوشش اور اصلاح کامنکر ہے وہ سمجھتاہے کہ اگر وہ ایک دفعہ گر گیا تو گر گیا.ایسے شخص کا بچنا بھی مشکل ہے.اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ خیال مت کرو کہ ہم نے تمہیں تدبیر کرنے اور بدی کا مقابلہ کرنے کی قوتیں اور طاقتیں عطا نہیں کیں.ہم نے تمہیں سب طاقتیںدی ہیں.اگر تمہاری نیت نیک ہو اور ان طاقتوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں استعمال کرو تو تم بدیوں سے بچ سکتے ہو.لیکن جو شخص تدبیر کا منکر ہے اور سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ایک گناہ بھی کر لیا تو پھر اس کا بچنا مشکل ہے ایسا انسان مختلف بدیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.جب وہ تدبیر کا ہی قائل نہیں تو وہ بدیوں سے بچنے کی کوشش ہی کیا کرے گا.مجھے یاد ہے بچپن میں میرا ایک دوست تھا مجھے اس کی بعض بدیوں کا پتہ لگا.میں نے اس سے پوچھا کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم میںفلاں فلاںبدیاں پائی جاتی ہیں ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے.لیکن میں جانتا ہوں کہ میں نے اتنے گناہ کئے ہیں کہ اب سزا سے بچ نہیں سکتا اور مجھے دوزخ میں جانا ہی ہے اس لئے اب میں گناہ خوب زور سے کرتا ہوں کہ اس زندگی کے تو لطف اٹھا لوں.میں نے اسے سمجھایا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی طاقتیں پیدا کر دی ہیں جن کے ذریعہ اگر وہ چاہے تو بدیوں پر غالب آسکتا ہے وہ سمجھ گیا اور اس کے بعد اس نے اصلاح کی کوشش کی جس سےاس کی اصلاح ہو گئی اور وہ بدیوں پر غالب آگیا.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُلًّا نُّمِدُّ هٰۤؤُلَآءِ وَ هٰۤؤُلَآءِ(بنی اسـرآءیل:۲۱) ہم
Page 558
ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ہم مومن کی بھی مدد کرتے ہیں اور کافر کی بھی مدد کرتے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مومن کو بھی روزی دیتا ہے اور کافر کو بھی روزی دیتا ہے.مومن کی کوشش کو بھی کامیاب کرتا ہے اور کافر کی کوشش کو بھی کامیاب کرتا ہے.خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم کافر کو بھی دنیوی فوائد کے حصول میں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں مدد دیتے ہیں.تو جو ہم سے ملنے کی کوشش کرے اسے ہم کیوں مدد نہیں دیں گے.جب خدا تعالیٰ اپنے دشمن کی بھی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے دوست کی مددکیوں نہیں کرے گا.حقیقت یہی ہے کہ تدبیر کا رستہ کھلا ہے.پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى (الاعلٰی:۱۰) تو نصیحت کرتا جا کیونکہ نصیحت ہمیشہ ہی فائد دیتی ہے.یہ تدبیر کبھی رائیگاں نہیں گئی.جب کسی قوم کے افراد نے اصلاح کر لی وہ ہمیشہ ہی کامیاب ہوئے.’’اِنْ‘‘ کہہ کر اس بات پرزور دیا گیا ہے کہ یہ قطعی اور لازمی بات ہے کہ نصیحت ہمیشہ کامیاب رہتی ہے.اسی طرح ایک اور جگہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے.وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْۤا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا۠ لِذُنُوْبِهِمْ١۪ وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ١۪۫ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ.اُولٰٓىِٕكَ جَزَآ ؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا١ؕ وَ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ.( اٰل عـمران :۱۳۶،۱۳۷) وہ لوگ جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بدی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں سے بچاسکے یہ جملہ معترضہ ہے آگے فرماتا ہے وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ وہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے لئے ایک راستہ نجات کا بنا چھوڑا ہے اگر وہ گناہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں.ا ن لوگوں کی جو اس نکتہ کو سمجھتے ہیں یہ جزا ہو گی کہ وہ اپنی کوشش اور جدو جہد سے خدا تعالیٰ کو پالیں گے اور ان کو مغفرت ملے گی اور باغات ملیں گے جن کے نیچےنہریں بہہ رہی ہوں گی اور یہ انعام عارضی نہیں ہو گا بلکہ وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے اور محنت کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہی ہوتا ہے یعنی جو کوئی بھی کوشش کرے گا اپنی کوشش میں ناکام نہیں ہو گا.دیکھو کتنا صاف رستہ کھولا گیا ہے جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے وہ بدیوں اور گناہوں پر غالب آجاتا ہے.میں کہتا ہوں اگر وہ غالب نہیں بھی آتا بلکہ شیطان سے لڑائی کرتا ہوا مر جاتا ہے تب بھی اسے یہی بدلہ ملے گا کیا کوئی سمجھدار انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ سپاہی جو لڑتےلڑتے فتح سے پہلے مر جاتا ہے اس پر ملک والے ناراض ہو تے ہیں ؟کیا ملک والے اس پر اس لئے ناخوش ہو تے ہیں کہ وہ فتح سے پہلے کیوں مر گیا؟ بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو سپاہی جنگ میں لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں ان کو بعد میں بڑے بڑے انعام ملتے ہیں.برطانوی فوج
Page 559
میں بعض کو وکٹوریہ کراس مل جاتے ہیں اور جرمنی میں آئرن کراس.پس حقیقت یہی ہے کہ جو شخص سچی کوشش کرتے کرتے مرجائے گو وہ اپنی کوشش میں پو ری طرح کامیاب نہ ہو وہ دوزخ میں نہیںجائے گا وہ تو خدا تعالیٰ کا سپاہی تھا جو لڑتے لڑتے مر گیا.وہ اپنی مرضی سے تو نہیں مرا.اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے موت آجائے.وہ الٰہی قانون کے مطابق لڑتا ہوا مرا ہے.وہ ایسا ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ مومن ہو نے کی صورت میں مرا.سپاہی جو لڑتے ہوئے مارا جائے وہ قابل تعریف ہو تا ہے یا قابل سزا ؟ جب وہ قابل تعریف ہو تا ہے قابل سزا نہیں ہو تا تو پھر جو شخص خدا تعالیٰ سے ملنے کی کوشش کرتا ہوا مر جاتا ہے اسے خدا تعالیٰ دوزخ میں کیوں ڈالےگا.احادیث میں آتا ہے کوئی شخص تھا جس نے نناوے قتل کئے تھے وہ توبہ کے لئے کسی عالم کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی.اس شخص نے کہا اگر میری توبہ قبول نہیں ہوسکتی تو میں تجھے بھی مار دوں گا.ایک گناہ اور زیادہ ہو گیا تو کیا ہوا.یہ کہہ کر اس نے اس عالم کو قتل کر دیا.اسی طرح اس نے ایک ایک کرکے بہت سے علماء کو مار دیا.ایک دفعہ کوئی شخص اسے ملا جس نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ پر فلاں عالم ہے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ قبول ہو تی ہے.تم اس کے پاس جاؤ.وہ شخص اس کے پاس جا ہی رہا تھا کہ رستہ میں ہی مر گیا.اس کی موت پر فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا.(یہ سب تمثیلی زبان کی بات ہے ) بہر حال احادیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوگیا.دوزخ والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ شخص دوزخی ہے اسے توبہ ابھی نصیب نہیں ہوئی اور جنت والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے کیونکہ یہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا ہے کہ رستہ میں مرگیا.آخر دوزخ اور جنت دونوں کے فرشتے خدا تعالیٰ کے پاس فیصلہ کرانے کے لئے پہنچے.خدا تعالیٰ نے فرمایا زمین ناپو جس طرف سے یہ شخص توبہ کرنے کے لئے چلا تھااگر وہ جگہ قریب ہے تو یہ دوزخی ہے اور اگر وہ جگہ جہاں یہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا قریب ہے تو یہ جنتی ہے.روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طنابیں کھینچ دیں اور اس جگہ کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا زیادہ قریب کر دیا.فرشتوں نے دونوں طرف کی زمین کو ناپا اور خدا تعالیٰ سے آکر کہا کہ جس طرف یہ شخص تو بہ کر نے کے لئے جا رہا تھا وہ زمین چھوٹی ہے خدا تعالیٰ نے حکم دیا پھر اسے جنت میں لے جاؤ(مسلم کتاب التوبۃ باب قبول توبۃ القاتل).اس تمثیل میں اس امر کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جو نجات کی کوشش کرتے ہوئے مر جاتا ہے اگر وہ گناہوں پر غالب آنے میں کامیاب نہ ہوا ہو تب بھی وہ جنتی ہی ہے بشرطیکہ جذبۂ صادق اور جدو جہد صحیح اور معیاری ہو لیکن جو شخص تدبیر اور کوشش کا ہی منکر ہو تو ا س کے بارہ میں آیت زیر تفسیرمیں فرماتا ہے کہ تُو اسے دیکھے گا کہ وہ بدیوں میں مبتلا ہو جائے گا.وہ سمجھ لے گا کہ میرے لئے اب بدیوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے
Page 560
لیکن اس کی رائے غلط ہے.مومن جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تدبیر کا راستہ کھلا رکھاہے.تدبیر سے انسان بدیوں پر غالب آسکتا ہے.اگر تدبیر کا راستہ کھلا نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لاحول، استغفار اور تعوّذ کیوں سکھاتا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لئے سکھائی ہیں کہ تدبیر کا راستہ ہر وقت کھلا ہے.جو کوئی بھی تدبیر کرے گا اوراپنے نفس کی اصلاح کرے گا وہ ضروربدی پر غالب آجائےگا.دین کے بارھویں معنے شاْن کے (۱۲) بارھویں معنے دین کے شَاْن کے ہیں.شَاْن کے معنے ہوتے ہیں بڑا کام.اَلْـخَطْبُ الْعَظِیْمُ بہت بڑی مہم (اقرب) اَلْـحَالُ وَالْاَمْرُ الَّذِیْ یَتَّفِقُ وَ یَصْلُحُ وَلَا یُقَالُ اِلَّا فِیْـمَا یَعْظُمُ مِنَ الْاَحْوَالِ وَ الْاُمُورِ (مفردات) جس کام میں ناکامی ہو اسے شاْن نہیں کہیں گے.بلکہ ہر وہ کام جس میں کامیابی کے لئے مواد بہم پہنچ جاتا ہے اور وہ ہو جایا کرتا ہے شاْن کہلاتا ہے.شاْن کا لفظ کبھی چھوٹے کام پر نہیں بولا جاتا ہمیشہ بڑے کام کے لئے بولا جاتا ہے.پس شاْن کے معنے ہوئے بڑی حالت یا وہ بڑا کام جو ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہو.قرآن کریم میں انہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو تا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِی شَاْنٍ (الرحمٰن:۳۰) ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ ایک خاص ارادہ کرتا ہے اور وہ جو ارادہ کرتا ہے اس کے لئے سامان بھی ضرور پیدا کرتا ہے اور ا س میں اسے ہمیشہ کامیابی ہو تی ہے.کُلَّ یَوْمٍ سے مراد انبیاء کا زمانہ ہے.یہ آیت سورۂ رحمٰن میںہے اس سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور پہلے انبیاء کے زمانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس نے دنیا کوانبیاء کے زمانوں میں تقسیم کردیا ہے اور ہر نبی کے زمانہ کے متعلق وہ ایک تقدیر جاری کرتا ہے جو اسی طرح پو ری ہو کر رہتی ہے اور اس سکیم کے منکر یا اس سے منہ پھیرلینے والے( ابتدائی زمانہ میں منکر اس کے مخاطب ہوتے ہیں درمیانی اور آخری زمانہ میں اس سکیم پر بظاہر ایمان لانے والے لیکن عملاً رو گردانی کرنے والے) خدا تعالیٰ کی گرفت میں آتے ہیں.پس اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ.فَذٰلِکَ الَّذِیْ یَدُعُّ الْیَتِیْمَ کے یہ معنے ہوں گے کہ مجھے بتا تو سہی اس شخص کا حال جو اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں ایک نئی سکیم جاری کرتا ہے اور اس زمانہ میں جو سکیم جاری کی گئی ہے وہ محمدی سکیم ہے.اگر کوئی شخص اس زمانہ کی سکیم یعنی محمدی سکیم کامنکر ہے توتُو دیکھے گا کہ اس میں ہر طرح کی بدی پائی جائے گی اور ایسا شخص مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گا.ویسے تو خدا تعالیٰ ہر زمانہ میں ہی اپنی قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے لیکن انبیاء کے زمانہ میں وہ خاص طور پر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور ان کے ذریعہ ایک خاص سکیم کو جاری کرتا ہے خواہ دشمن کتنے ہی روڑے کیوں نہ
Page 561
اٹکائیں خدا تعالیٰ کی سکیم پوری اور کامیا ب ہو کر رہتی ہے.ایک سکیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میںجاری کی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کتنے طاقت ور تھے فرعون جیسا طاقت ور بادشاہ آپ کے مقابلہ میں تھا لیکن خدا تعالیٰ کی سکیم کے مقابلہ میںنہ تو فرعون کامیاب ہوسکا اور نہ اسے چھوڑ کر آپ کی امت ہی جیت سکی.جب آپ کی قوم نے کہہ دیا اِذْهَبْ اَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلَاۤ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ(الـمائدۃ:۲۵) اے موسیٰ جا تو اور تیرا خدا دونوں لڑو ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے.ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے اپنی کامیابی اور بہتری کا سامان ہم خود پیدا کر لیں گے.تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ جنگلوں میں چالیس سال تک بھٹکتی رہے کہاںاس کی وہ حالت تھی کہ مصر سے نکلنے کے بعد وہ کامیابی پر کامیابی حاصل کرتی رہی.لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اسے جنگلوں میں بھٹکنا پڑااور کوئی صورت بھی اس کی کامیابی کی نہ رہی یہاں تک کہ اس نے حضرت یو شع علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی.یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا آپ کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی.مخالفوں نے اپنا زور لگایا مگر وہ کامیاب نہ ہوئے خدا تعالیٰ کی ہی سکیم کامیاب ہوئی اور یہودیوں کی بادشاہت اس وقت تک نہ آئی جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستہ پر چل نہ پڑے ( سوائے موجودہ زمانہ کی عارضی کامیابی کے جس کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے دیکھو تفسیر سورۂ بنی اسرائیل) جتنی لمبی تکلیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اٹھائی ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے.تین سو سال تک اس نے ذلت کی زندگی گذاری.بعض دفعہ سات سات سال تک وہ سطح زمین سے اسّی فٹ نیچے گیلی زمین میں غاروں میں چھپی رہی.میں نے ان جگہوں کو اٹلی میں خود دیکھا ہے (ان کو کیٹا کومبز کہتے ہیں ) ایسی خطرناک جگہیں ہیں کہ وہ تمہارے واہمہ میں بھی نہیں آ سکتیں.اگر وہ تکالیف ہماری جماعت کو اٹھانی پڑیں تو مجھے خوف ہے کہ بہت سے احمدی احمدیت چھوڑ دیں.لیکن عیسائیوں میں سے ایک مخلص طبقہ ( ان میں سے کمزور ڈر سے مسیحیت چھوڑ دیتے تھے) وہاںسات سات سال تک متواتر رہا ہے تا ان گڑھوں اور غاروں میں چھپ کر کسی طرح ان کا ایمان بچ جائے.غاروں کے اندر ہی ان کے گرجے تھے چوری چوری وہ باہر نکلتے تھے اور اپنے ہمدردوں کے ذریعہ شہر سے غلّہ منگواتے تھے.غاروں میں بالکل اندھیرا تھا وہ شمعیں جلا جلا کر گذارہ کرتے اور دن رات وہیں گذار دیتے تھے.اس جگہ کے دیکھنے کے بعد کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ عیسائیوں کو اس نے ایک لمبے عرصہ تک
Page 562
بادشاہت اور حکومت کیوں دی.یہ تو ان کےباپ دادوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بھلایا نہیں.میں جب اس جگہ کو دیکھنے کے لئے گیا تو ابھی دو درجے ہی نیچے گیا تھا کہ مجھ میں آگے جانے کی طاقت نہ رہی پھر بھی میری آگے جانے کی نیت تھی مگر میرے بعض ساتھیوں نے زور سے کہا کہ اگر آپ اور آگے گئے تو ہم بیمار ہو جائیں گے اس لئے ہم واپس آگئے.دو درجے ہی جانے میں ہمارے دل بیٹھ گئے اور ہمارے جسموں میں کوئی طاقت نہ رہی ستّر میل لمبے غارتھےاور عیسائی وہیں رات دن رہتے تھے وہیں بچے پیدا ہورہے تھے وہیں ان کے گرجے تھے جگہ بہ جگہ یہ کتبے لگے ہوئے ہیں کہ میرے بیوی بچے بہن بھائی یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ روما کی پولیس کسی مخبر سے خبر معلوم کر کے یہاں آئی اور اس نے ان سب کو مار دیا.میں کسی طرح بچ گیا اب میں یہاں کتبہ لگاتا ہوں تا دیکھنے والے ان کے لئے دعا کریں.کسی کتبہ پر یوں لکھا ہے، یہاں ہمارے پادری صاحب وعظ کر رہے تھے کہ انہیں روما کی پولیس نے شہید کر دیا ان کی یادگار کے طور پر میں یہ کتبہ لگاتا ہوں.کیا ہی عجیب قسم کا استقلال ہے، کیا ہی عجیب قسم کی قربانی ہے اس کے بدلہ میں اگر اس قوم کو ایک لمبا عرصہ حکومت مل گئی تو اس کا خدا تعالیٰ پر کوئی الزام نہیں آسکتا.پس ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سکیم جاری کی جاتی رہی ہے اور جو بھی اس کےمقابلہ میں اٹھتا رہا ہے ناکام ہوتا رہا ہے.حضرت کرشن علیہ السلام، حضرت رام چند علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی.حضرت زردشت علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک سکیم جاری ہوئی.کُلَّ یَوْمٍ ھُوَ فِیْ شَاْنٍ.اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں ایک نئی سکیم جاری کرتا ہے اور جو اس پر نہیں چلتا وہ گناہ میں ترقی کرے گا نیکی میں ترقی نہیں کرے گا.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلےمخالف عرب تھے.ان میں سے جنہوں نے آپ کو مان لیا وہ کامیاب ہو گئے اور ترقی کر گئے حضرت ابو بکر ؓ اورابو جہل میں آخر کیا فرق تھا بلکہ ابو جہل اپنی قوم میں حضرت ابو بکر ؓ سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت ابو بکر ؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ابو جہل آپ کا انکارکر کے کہاں سے کہاں جا گرا.کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلا ں قوم ایسا کرتی ہے وہ کیوں بچ گئی.فلاں قوم بد کاریاں بھی کرتی ہے اور دوسرے کام بھی کرتی ہے اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے تو ہم اسلام کے احکام یعنی نمازوں، روزوں اور پردہ وغیرہ کے احکام پر عمل کرنے کے بغیر کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے ؟اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے مطابق اس سکیم کا پہلا حصہ تھا بعد کے زمانہ میںیعنی جب ایک دفعہ نبی کی قوم غالب آگئی تو اب سکیم کا دوسرا حصہ چلتا ہے جونبی کے
Page 563
ماننے والوں کے متعلق ہے اور وہ یہ کہ اگر وہ عملاً دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو زیادہ سزا دیتا اور ان کے دشمن کا خیال چھوڑ دیتا ہے اور ظاہری ماننے والوں سے فرماتا ہے کہ وہ قومیں اس زمانہ کی سکیم کے مطابق چلنے کی دعوے دار نہیں.اس سکیم کے مطابق چلنے کے دعوے دار تم ہو.تم اس سکیم کے پر زے ہو، وہ تو اس کے پرزے نہیں.یہ قانون تمہارے لئے ہے ان کے لئے نہیں.جو قومیں اس سکیم کی مخاطب ہی نہیں یا جو ابھی تک مخاطب نہیں ہوئیںوہ اگر اس کے خلاف چلتی ہیں تو انہیں کوئی سزا نہیں.تو چونکہ ان کی سزا کی سکیم زمانہ نبوی میں پوری ہو چکی اب ان کو ان کی بدعملیوں کی وجہ سے سزا دینے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ تم کو تمہاری بد عملیوں کی سزا دینے کے ضرورت ہے.اس زمانہ میں مسلمان اگرترقی کر سکتے ہیں تو اسلام کے احکام پر چل کر ہی کر سکتے ہیں.مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر ترقی نہیںکر سکتے.مسلمان تو اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری شدہ سکیم کے پر زے ہیں اگر وہی اس سکیم کو چھوڑ دیں تو یہ نظام کیسے چل سکتا ہے.اگر مسلمان مذہب پر چلے بغیر ترقی پا سکتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اس سکیم کے جاری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان اسلام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے.لیکن جب احمدیت پورے طور پر قائم ہو جائے گی اس وقت دوسرے مسلمان اس سکیم کے پر زے نہیں رہیں گے اور وہ اس کے بغیر بھی ترقی کر سکیں گے.مگر جب تک احمدیت دنیا میں قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک دوسرے مسلمان بھی اس سکیم کے ایسے ہی پر زے ہیں جس طرح احمدی اس سکیم کے پرزے ہیں اور وہ اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوسکتے.دوسری قومیں اسلام کے بغیر ترقی کر سکتی ہیں کیونکہ وہ اس سکیم کے پر زے نہیں وہ تو پہلے سے خدا تعالیٰ کو چھوڑ چکی ہیں ان کے مزید بگڑ جانے سےموجودہ زمانہ کے مذہب یعنی اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا.لیکن اگرمسلمانوںکو بھی اسلام چھوڑنے پر دنیا کی ترقی اور غلبہ مل جائے تو وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں گے.اس صورت میں خدا تعالیٰ کی ہدایت کاکوئی حامل نہ رہےگا اور محمدی سکیم ناکام ہو جائے گی.پس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلام کے بغیر ترقی نہ دے گا تا ان کو مجبوراً اسلام کی طرف لوٹنا پڑے.اور دنیا کے دکھ آخر انہیں خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں اور اسلام کے ذریعہ سے جو خدا کی سکیم جاری ہوئی ہے وہ دنیا میں زندہ اور قائم رہے.اگر عیسائی اپنے مذہب پر عمل نہیںکرتا تو وہ باوجود بگڑنے کے بےشک ترقی کرتا چلا جائے گا اگر ہندو اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتا تو وہ باوجود بگڑنے کے بےشک ترقی کرتا چلا جائے گا کیونکہ وہ مذاہب تو اپنی ذات میں بھی بگڑ چکے ہیں.ان کے بگڑنے سے خدا تعالیٰ کی سکیم کی موٹر خراب نہیں ہو تی لیکن اگر مسلمانوں کو خدا تعالیٰ با وجود بگڑنے کے ترقی کرنے دے تو پھر اس کی موٹر رک جائے گی کیونکہ مسلمان اس کی موٹر کے پرزے ہیں.اگر ان کو غافل ہو نے دیا جائے تو موٹر بھی خراب ہو جائے گی.پس اللہ تعالیٰ
Page 564
فرماتا ہے مجھے بتا تو سہی اس شخص کا حال جو شان الٰہی کا انکار کرتا ہے اس سلسلہ کا انکار کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں جار ی کیا ( یہاں سلسلہ سے مرادسلسلہ محمدی ہے کیونکہ جو سلسلہ خدا تعالیٰ نے اس زمانہ میں جاری کیا ہے وہ سلسلہ محمدی ہی ہے ) اگر کوئی شخص ایسا ہے جو سلسلہ محمدیہ کا انکار کرتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوسکتا اس زمانہ میں اگر ترقی اورکامیابی حاصل ہو گی تو سلسلہ محمدیہ پر چل کر ہی ہو گی اور اس سلسلہ کا پر زہ بننے کی صورت میں ہی ملے گی (جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس سے مراد اسلام کے غلبہ سے پہلے کا زمانہ ہے اس کے بعد سکیم کا دوسرا حصہ چلتا ہے ) فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَۙ۰۰۳ وہی شخص تو یتیم کو دھتکارا کرتا ہے.حلّ لُغات.یَدُعُّ دَعَّ سے مضارع کا صیغہ ہے اور دَعَّہُ دَعًّا کے معنے ہیں دَفَعَہُ دَفْعًا عَنِیْفًا.اس کو سختی سے ہٹایا.وَفِی الْاَسَاسِ ’’ دَعَّ الْیَتِیْمَ‘‘ دَفَعَہُ بِـجَفْوَۃٍ.’’اساس‘‘ لغت کی کتاب میں دَعَّ الْیَتِیْمَ کے معنے یہ لکھے ہیں کہ یتیم کو دھتکارا اور اس سے برا سلوک کیا.(اقرب) تفسیر.اس آیت میں بتایا گیاہے کہ جو دین کی تکذیب کرتا ہے وہی یتیم کو دھتکارنے والا ہے فَاء جو ذَالِکَ سے پہلے آئی ہے بتاتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی جملہ محذوف ہے کیونکہ ظاہر جملہ یعنی اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ ’’فَاء ‘‘کی وجہ نہیں بن سکتا.یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مفسرین کے نزدیک اس جملہ کی مختلف تشریحات ہیں.صاحب کشاف یعنی علامہ زمخشری جو تفسیر کے لحاظ سے تو اعلیٰ پایہ کے نہیں سمجھے جاتے مگر نحو اور لغت کے امام مانے جاتے ہیں ان کے نزدیک یہاں فَاء سے پہلے اِنْ لَمْ تَعْلَمْ کا جملہ محذوف ہے یعنی اے مخاطب اگر تو نہیں جانتا کہ وہ کون شخص ہے جو دین کی تکذیب کرتا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں یہ یہ علامات پائی جاتی ہیں.اَرَءَیْتَ الَّذِیْ کے متعلق مفسرین کا ایک اعتراض اور اس کا جواب بعض مفسرین نے اس آیت پر یہ اعتراض وارد کیا ہے اور وہ یہ کہ اِنْ لَمْ تَعْلَمْ کا جملہ شک پر دلالت کرتا ہے لیکن خدا تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے اسے شک نہیں ہو سکتا کہ مخاطب اس امر کو جانتا ہے یا نہیں.اس اعتراض کے مختلف لوگوں نے مختلف جواب دیئے ہیں مگر میرے نزدیک اس جگہ اس جملہ کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ مخاطب ایک مخصوص شخص نہیں بلکہ فرداً فرداً تمام بنی نوع انسان یا قرآن کریم کے پڑھنے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب مخاطب متعدد
Page 565
ہوں تو بعض کو اس مضمون کا جس کا ذکر اس آیت میں ہے علم ہوگا اور بعض کو علم نہیں ہو گا.پس جب متعدد مخاطبین کا علم اس مضمون کے بارہ میں مختلف ہو نا ممکن ہے تو یہ آیت متکلم یعنی اللہ تعالیٰ کے شک پر دلالت نہیںکرتی بلکہ مخاطبین کی مختلف حالتوں پر دلالت کرتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے مخاطب کہ اگر تو اس سوال کا جواب نہیں جانتا تو اس کا جواب یہ ہے.اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ بتایاجا چکا ہے اَرَءَیْتَ میں ہمزہ استفہام کا نہیں بلکہ توکید کا ہے اور محاورہ میں اس کے معنے ہیں مجھے بتا تو سہی.پس جب اس جگہ سوال کیا ہی نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ کے متعلق شک کا الزام پید اہی نہیں ہو تا.اَرَءَیْتَ میں مخاطب صرف آنحضرتؐنہیں اس جگہ یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گو اَرَءَیْتَ میںحرف تاء استعمال کیا گیا ہے جوضمیر مخاطب واحد ہے مگر اس سے مراد بہت سے افراد ہیں جیسا کہ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا (بنی اسـرآءیل :۲۴) یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرے ماںباپ بوڑھے ہوجائیں تو تُو انہیں اُف تک مت کہیو اور انہیںمت جھڑکیو.ظاہر ہے کہ یہ لفظی معنے بالکل غلط ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے بلکہ ان کی والدہ بھی ان کے بچپن میں فوت ہو گئی تھیں اور قرآن کریم میں سورۃ وَ الضُّحٰى میں آپ کے یتیم ہو نے کا ذکر آتا ہے.پس آیت فَلَا تَقُلْ میں خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اور جب آپ سے خطاب نہیں تو لازماً سب مسلمانوں سے خطاب ہے.اور ضمیر واحد لانے کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو فرداً فرداً مخاطب کیا گیا ہے تاکہ مضمون پر خاص زور پڑے اور مطلب یہ ہے کہ اے زید تو بھی اور اے بکر تو بھی اس حکم کو غور سے سن لے کہ اگر تیرا باپ اور تیری ماں بوڑھے ہو جائیں اور بڑھاپے سے ان کا مزاج چڑچڑا ہو جائے تو تُو ان کے غصہ کو برداشت کر لیا کر اور ان کی باتوں کو سن کر اتنا بھی نہ کہا کر کہ ’’بس جانے دیجئے‘‘ غرض کبھی کبھی مفرد کا لفظ جمع کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور اس وقت تمام افراد انسانی یا افراد قوم فرداً فرداً مخاطب ہو تے ہیں اسی قاعدہ کے مطابق اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یُکَذِّبُ بِالدِّیْنِ میں بھی فرداً فرداً تمام مسلمان یا تمام انسان مراد ہیں اور کہا گیا ہے کہ جو جانتا ہے وہ بھی یاد رکھے اور جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے کہ تکذیب دین کرنے والامختلف گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے حوفی جونحو کے علماء میں سے ہیں کہتے ہیں کہ اس جگہ ہمزہ انکار کا نہیں بلکہ تاکید کا ہے(بحر محیط زیر آیت ھذا) (میں اس کے بارہ میں پہلے لکھ چکا ہوں) اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ کیا تو نے وہ شخص دیکھا ہے جو تکذیب دین کرتا ہے یعنی تجھے یقیناً معلوم ہے کہ تکذیب دین کرنے والا کون ہے.ہم اس کے انجام کی تجھ کو خبر دیتے ہیں کہ وہ قسم قسم کے گناہوں
Page 566
میں مبتلا ہو جائے گا ان معنوں کے رو سے یہ آیت ایک پیشگوئی پر مشتمل سمجھی جائے گی.اور اس طرف اشارہ سمجھا جائے گا کہ اسلام کی مخالفت کرنے والے قسم قسم کے گناہوں میںمبتلا ہوجائیں گے اور ایسا ہی ہوا.یتیم کو دھتکارنا اور اس سے بد سلوکی کرنا قرآن کریم کے نزدیک بد ترین اعمال میں سے ہے.اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتا ہے.مثلاً اَمَّا الْیَتِیْمَ فَلَاتَقْھَرْ(الضحٰی:۱۰) قرآن کریم میں یتیم کے متعلق جتنے بھی لفظ آئے ہیں وہ دھتکارنے، رد کرنےاور دبا دینے کے آئے ہیں.اس پر ایک سوال پیدا ہو تا ہے کہ یہ تعلیم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہو نے کا ردّ عمل تو نہیں؟اور یہ سوال ان لوگوں نے اٹھایا ہے جن کے نزدیک قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کی آواز ہے، خدا تعالیٰ کی آواز نہیں اور ایسے لوگ دو قسم کے ہیں بعض لوگ مسلمان ہیں اور بعض غیر مسلمان.جومسلمان ہیں وہ کہتےہیں کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پاک اور منزّہ تھی اس لئے جب آپ نے دنیا کی خرابیوںکو دیکھا تو ان کے خلاف آپ کے دل میں جوش پیدا ہو گیا.آپ نے احتجاج کیا اور ان کے خلاف آواز اٹھائی اور یہی آواز جو آپ کی نیک اور پاک فطرت کی طرف سے اٹھائی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی آواز تھی دوسری قسم کے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین اور ہو شیار آدمی تھے.جب آپ نے دنیا میں مظالم دیکھے، خرابیاں اور برائیاں دیکھیں تو آپ کے اندر ان کا ردّ عمل پیدا ہو گیا اور ان سے متاثر ہو کر جو باتیں آپ نے کہیں وہ قرآن کریم ہے لیکن آپ اپنے خیال میں نعوذ باللہ من ذالک بوجہ کمی علم کے اسے خدا تعالیٰ کی آواز سمجھ کر کہتے تھے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے.ورنہ الہام وغیرہ کوئی نہیں ہو تا تھا.آپ ذکی الحس تھے، حاد الطبیعت تھے اور آپ کی فطرت صاف تھی.پس آپ کی صاف فطرت نے اچھی باتیں پیدا کرلیں اور آپ نے خیال کر لیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سےہیں.پس یہاں یہ اعتراض ہو تا ہے کہ آپؐجوبار بار کہتے ہیں کہ یتیم کی خبر گیری کرو، یتیم کی خبر گیری کرو.تو کیا آپ کے یتیم ہو نے کا یہ ردّ عمل تو نہیں.ہرایک چیز کا ایک ردّ عمل ہوتا ہے اسی ردّ عمل کے نتیجہ میں بعض دفعہ انسان اس کے الٹ کام کرتا ہے اور بعض دفعہ اس کے مطابق کام کرتا ہے.بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے لوگ ظلم کرتے جارہے ہیں وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہوجاتے ہیں.ان کی طبائع میں اس کا ردّ عمل اس طرح پیدا ہو تا ہے کہ وہ بھی ظلم کرنے لگ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم سب ظالموں سے بدلہ لے رہے ہیں اور بعض دفعہ ایسا ہو تا ہے کہ جب وہ مظالم کو دیکھتے ہیںتو انصاف کی روح ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ظلم کے خلاف ان کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے خلاف ہر ممکن قربانی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں.غرض علم النفس کے ماتحت انسان کے اندر جو ردّ عمل
Page 567
ہوتا ہے وہ کبھی تو اصلی فعل کے مطابق ہو تا ہے اور کبھی اس کےمخالف ہوتا ہے.پس اس موقع پر بعض منکرین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ یتیم کی خبر گیری کرو، یتیم کی خبر گیری کرو.کیوں نہ یہ سمجھا جائے کہ یہ تعلیم آپ کے یتیم ہو نے کا ردّ عمل ہے یعنی یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں آپ کی فطرت کی آواز ہے.کیونکہ آپ یتیم تھے آپ پر جو ظلم کئے گئے آپ کے دل میں یہ خیال پید اہوا کہ یہ میرے یتیم ہو نے کے سبب سے ہے.آپ کا دل نہایت حساس تھا اس نے دنیا سے ان مظالم کا بدلہ لینا چاہا، آپ کے اندر ایک جوش اٹھا آپ نے دیکھا کہ آپ جیسے اور بھی یتیم ہیں جو لوگوں کے ظلموں کا شکار ہو رہے ہیں.ان پر سختیاں کی جاتی ہیں تکالیف دی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے اور مظالم توڑے جاتے ہیں.آپ نے کہا بہت اچھا اب میں ان ظلموں کا بدلہ لوں گا.میں انہیں طعنے دوں گا، ان پر الزام لگاؤں گا، ان کی برائیاں بیان کروں گا اور یتیموں کی مدد کروں گا.آپ کے اندر جوش پیدا ہو گیا.آپ کی طبیعت صاف تھی اس کے اندر سے ایک آواز اٹھی یہ طبعی آواز تھی جو قدرتی طور پر آپ کے اندر سے اٹھی.مگر آپ نے ناواقفیت کی وجہ سے (نعوذباللہ من ذالک)اسے الہام سمجھ لیا.ہم کہتے ہیں یہ درست نہیں کہ قرآن کریم آپ کی فطرت کی آواز ہے اور اس کی تعلیم اس ردّ عمل پر مشتمل ہے جو اس زمانہ کے حالات کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےدل میں پیدا ہوا.گو ہم عقیدۃً بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے مگر علم ظاہر کے لحاظ سے بھی ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم نفسیاتی ردّ عمل کا نتیجہ نہیں ہے.یتامیٰ کے متعلق اسلامی تعلیم کسی ردّ عمل کا نتیجہ نہیں پس مسلمان متشکک کے لئے تو ہمارا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں خدا تعالیٰ کا کلام ہے اس لئے اس کے ’’ردّ عمل‘‘ ہو نے کا خیال بالبداہت باطل ہے.کیا خدا تعالیٰ یتیم یا مسکین ہے کہ یتامیٰ اور مساکین پر جو ظلم ہو تے تھے ان کے جواب میں اس کے دل میں بھی ایک ردّ عمل ہوا اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ردّ عمل کا اظہار فرمایا.لیکن اسلام کے منکر کے اعتراض کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے دعویٰ کو نظر انداز کر کے عقلاً بھی یہ اعتراض درست نہیں ہے کیونکہ واقعات سے ثابت ہے کہ یتامیٰ وغیرہ کےخلاف قرآن کریم کی تعلیم انتقامی نہیں اصلاحی ہے.ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یُتم کے زمانہ کو دیکھتے ہیںتو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یُتم ایسا نہیں تھا کہ اس کے خلاف آپ کے اندر کوئی ردّ عمل پیدا ہو تا.اگر آپ کے اور رشتہ دار نہ ہوتے یا ایسے رشتہ دار ہو تے جو آپ پر ظلم کرتے، آپ پر سختی کرتے اور تکالیف دیتے.تب تو یہ اصلاحی آواز نہیں انتقامی آواز ہو تی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
Page 568
آپ پر ایسا دن آیا ہی نہیں کہ جب آپ نےیُتم کو محسوس کیا ہو.بے شک آپ یتیم تھے لیکن ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیئے تھے جن کی وجہ سے آپ نے یُتم محسوس نہیںکیا چنانچہ آپ کے والد کی وفات پر آپ کے دادا نے آپؐکو اپنا بیٹا بنا لیا اور آپ اپنی والدہ کے ہی انتظام میں رہے آپ کے دادا نے یہ نہیں کیا کہ آپ کو والدہ سے چھین لیا ہو.جیسے بعض ظالم کرتے ہیں ظاہری طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یتیم کی پرورش کر رہے ہیں لیکن در اصل ماں کو دکھ پہنچانا ان کا مقصود ہوتا ہے.اگر عبد المطلب آپ کو آپ کی والدہ سے لےلیتے تو بظاہر ماں کو دکھ ہوتا لیکن اس کا اثر آپ پر بھی پڑتا.اگر ایساہوتا تو ردّ عمل کا سوال پیدا ہو سکتا تھا.آپ دوسرے بچوں کو ماں ماں کہتے سنتے اور ماں باپ کا اپنے بچوں سے نیک سلوک دیکھتے تو آپ کے دل میں بھی یہ خواہش پیداہوتی کہ کاش میری بھی ماں ہوتی یا یہ خیال پیدا ہوتا کہ اگر میر ابھی باپ ہو تا تو مجھے کوئی میری ماں سے کیوں چھینتا.لیکن عبد المطلب نے ایسا نہیں کیا.آپ کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کو آپ کی والدہ کے قبضہ میں ہی رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے سمجھو.لیکن اس کی پر ورش کاانتظام تم ہی کرو کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ.یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہوگیا ہے جب واقعات یہ تھے تو قدرتی بات ہے کہ آپ کے اندر اپنے یتیم ہو نے کا ردّ عمل پیدا نہیں ہوسکتاتھا.پھر مکہ کے دستور کے مطابق بچوںکو کچھ عرصہ کے لئے مکہ سے باہر بھیج دیا جاتا تھا کہ وہ بچپن گاؤں میں گذار آئیں تا ان کی زبان اچھی ہو جائے اور صحت بھی اچھی ہو جائے.گاؤں والوں کی زبان زیادہ صاف ہو تی تھی.عرب اور دوسرے ملکوں میں یہ فرق ہے کہ دوسرے کسی ملک کی دیہاتی زبان صاف نہیں ہو تی بلکہ شہری زبان صاف ہو تی ہے.لیکن عرب میں شہروں کی زبان ادنیٰ سمجھی جاتی تھی اور گاؤں کی زبان اعلیٰ سمجھی جاتی تھی اصل میں تو سب کا سب عرب ہی زبان کے لحاظ سے ایک سطح پر تھا.شہر اور گاؤں کی بولی ایک ہی قسم کی تھی لیکن شہر والے لوگ چونکہ غیر ممالک کے لوگوں سے ملتے جلتے رہتے تھے اس لئے ان کی زبان میں دوسری زبانوں کے بعض الفاظ مل گئے تھے اس لئے عرب میں یہ دستور تھا کہ بچپن میں پانچ سات سال تک کے لئےبچوں کو مکہ سے باہر بھیج دیا جاتا تھا تا مضبوط ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے ان کی صحت اچھی ہو جائے اور گاؤں میں رہنے سے زبان بھی دوسری زبانوں کے اختلاط سے محفوظ رہے مکہ سے باہر کے جو گاؤں تھے ان کی عورتیں آتی تھیں اور مکہ والے انہیں اپنے بچے دے دیتے تھے اور وہ ان کو پال کر لے آتی تھیں.محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی ایسا ہی کیا.آپ کی والدہ نے بھی چاہا کہ وہ اپنا بچہ کسی عورت کو دے دیں تا وہ اسے پال کر لے آئے.لیکن چونکہ آپ یتیم تھے اس لئے کوئی عورت اس خیال سے آپ کو لینے کے لئے تیار نہیں تھی کہ ان کے پالنے کے بعد انعام کون دے گا.ان باہر سے
Page 569
آنے والی عورتوں میں سے ایک حلیمہ بھی تھیں.آپ غریب خاندان کی فرد تھیں.آپ اس لئے مکہ آئی تھیں کہ کسی مال دار کا بچہ مل جائے تو پال پوس کر اچھا انعام حاصل کریں.آپ حضرتؐکی والدہ کے پاس بھی گئیں انہوں نے ان کو سب حالات ٹھیک ٹھیک بیان کر دیئے جس پر وہ مایوس ہو کر دوسرے بچہ کی تلاش میں چلی گئیں لیکن چونکہ بچہ والے بھی دائیوں سے پوچھتے تھے کہ کیا وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں.کیونکہ اگر وہ خود کھاتے پیتے نہ ہوں تو بچہ کی پرورش اچھی طرح نہیں کر سکتے لیکن حلیمہ چونکہ خود بھی غریب تھیں مکہ کی کسی عورت نے ا ن کو اپنا بچہ دینا پسند نہ کیا.غرض ایک طرف آپ کو یتیم ہونے کی وجہ سے ہر دائی ردّ کرتی گئی اور دوسری طرف حلیمہ کو غریب ہو نے کی وجہ سے سب گھر ردّ کرتے گئے.نتیجہ یہ ہوا کہ سارا دن پھر کر اور ناکام رہ کر حلیمہ آخر آپؐکی والدہ کے پاس آئیں اور کہا کہ لاؤ بچہ ہم اسے پالیں گے چونکہ دوسری دائیاں آپؐکو ردّ کر چکی تھیں آپؐکی والدہ نے بھی اس تجویز کو پسند کر لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ خوش قسمت، حلیمہ جس کی قسمت میں ایک تاریخی وجود ہونا لکھا تھا کی گود میں ڈال دیئے گئے.یہ ایک الٰہی تدبیر تھی.اگر آپ کو دائی نہ ملتی اور بچپن میں کچھ سال گذارنےکے لئے آپ کوکسی گاؤں میں نہ بھیجا جاتا تب تو ہو سکتا تھا کہ آپ کے اندر یُتم کا خیال پیدا ہو تا.آپ دوسرے بچوں کو دیکھتے کہ وہ مکہ سے باہر گاؤں میں رہے ہیں اچھے ماحول میں رہے ہیں.ان کی زبان اچھی ہے، ان کی صحتیں اچھی ہیں تو خیال کرتے کہ مجھے بھی کوئی پچپن میں گاؤں بھیجتا، میں بھی ورزش کرتا، دودھ پیتا تو میری بھی صحت اچھی ہو تی، زبان صاف ہو تی مگر ایسا نہیں ہوا.اس لئے کہ میں یتیم تھا اچھا اب میں اس کا بدلہ لوں گا.مگر آپؐکے دل میں تو یہ زخم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اور جب آپ کو اپنے یُتم کا احساس ہی نہیں ہوا تو آپ کے اندر ا س کا ردّ عمل کس طرح پیدا ہوا.جب آپ حلیمہ کے گھر میں گئے تو اس کی حالت آپ کے جانے سے بدل گئی اور گھر میں برکت آگئی اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ سب کچھ اس بچہ کی برکت سے ہے.حلیمہ، اس کا خاوند اور سب گھر کے چھوٹے بڑے آپؐکے گرویدہ ہو گئے اور آپؐپر نثار ہو نے لگے.اگر گھر میں غربت رہتی اور آپ کو دوسرے بچوں سے کم آرام ملتا تب تو ممکن تھا کہ آپ کے دل میں ردّ عمل پید اہوتا (السیرۃ النبویۃ لابن ھشام ولادۃ رسول اللہ ورضاعتہ).اسی طرح جب آپ اپنے گھر واپس آئے تو دادا دل و جان سے فدا ہو کر آپ کی خدمت کرتے.آپ کی والدہ فوت ہو گئیں تو آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو اپنے پاس لے گئے.عبد المطلب کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کا اتنا رعب ہوتا تھا کہ ہم میں سے جوان سے جوان کی بھی طاقت نہیں ہو تی تھی کہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھائے.عرب میں بڑوں کا بہت ادب کیا جاتا تھا اور کروایا جاتا تھا لیکن
Page 570
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی وجہ سے بعض دفعہ دادا سے کھیلتے ہو ئے ان کے کندھوں پر چڑھ جاتے.آپ کے بیٹے سرخ سرخ آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے مگر حضرت عبد المطلب فرماتے خبردار میرے اس بچے کو بری نگاہ سے نہ دیکھنا.غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھی ایسالمحہ نہیں آیا کہ جب آپ کو اپنے یُتم کا احساس پیدا ہوا ہو.جب حضرت عبد المطلب فوت ہوئے آپؐکی عمر اس وقت آٹھ نو سال کی تھی(السیرۃ النبویۃ لابن ھشام وفاۃ عبد المطلب).وفات سے کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور فرمایا میں تم پر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اعتبار کرتا ہوں.یہ میری امانت ہے اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا، دیکھنا اس کا دل میلا نہ ہو.ابوطالب نےبھی اپنے عہد کو نباہا.آپ اپنے بچوں کو اپنے بچے نہیں کہتے تھے.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بچہ کہا کرتے اور آپ سے بہت پیا رکیا کرتے تھے.تاریخ بتاتی ہے کہ آپؐکوہ وقار تھے آپ کی چچی کو تو آپ سےا تنی محبت نہیں تھی اور نہ ہی آپ کے داد ا نے اسے آپ کے متعلق کوئی وصیت کی تھی اور نہ ہی چچی کا رشتہ کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے.لیکن تاریخ سے یہ ثابت نہیں کہ آپ کی چچی نے آپ پر کبھی کوئی سختی کی ہو آپ کی چچی جب گھر میں کوئی چیز بچو ں میں تقسیم کرتیں تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیتیں شاید اس لئے کہ وہ چھوٹے تھے.اس وقت سب بچے اپنی ماں سے چمٹ جاتے اور کہتے ہمیں بھی دو ہمیں بھی دو.لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے رہتے اور اس شور میں حصہ نہ لیتے تھے(السیرۃ الـحلبیۃ ذکر وفاۃ عبد المطلب وکفالۃ عمہٖ).بعض دفعہ ایسے موقع پر ابو طالب بھی آجاتے تھے آپ کو ایک طرف بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو طالب خیال کرتے کہ شاید اس بچہ کا خیال ہے کہ میرا ا س گھر میں کوئی حصہ نہیں.گو آپ کا اس طرح بیٹھنا وقار کی وجہ سے تھا جو بچپن سے آپ کو حاصل تھا.بہر حال ابو طالب کے دل میں محبت جوش مارتی اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر آگے لاتے اور کہتے تم نے میرے بچہ کو اب تک کچھ نہیں دیا.ابو طالب ہمیشہ آپؐکو اپنابچہ ہی کہتے تھے.اس حالت میں آپ کویُتم کا احساس کس طرح ہو سکتا تھا.اگر کوئی احساس ہو سکتا تھا تو یہی کہ میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے.خواہ ان سے وہ سلوک خدا نے ہی کروایا تھا لیکن آپ تو یہ سمجھتے تھے کہ جس گھر میں مَیں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ محبت اور پیا ر سے پیش آتے ہیں اور میرے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں.غرض ایسا موقع کوئی آیا ہی نہیں کہ آپ کے اندر یُتم کااحساس پیدا ہوسکتا ہو.پس یُتم کے احساس کی وجہ سے یہ تعلیم پیدا نہیں ہوئی کہ اسے انتقامی کہا جائے یا نفسیاتی.لیکن اگر بفرض محال اسے نفسیاتی بھی مان لیا جائے تو پھر یہ اصلاحی تھی انتقامی نہیں تھی.اس صورت میں یہ کہا جائے گا آپ نے خیال کیا کہ میرے رشتہ دار
Page 571
اتنے شریف اور اچھے تھے کہ انہوں نے میرے اندر یُتم کا احساس پیدا نہیں ہو نے دیا.اب میرا بھی فرض ہے کہ میں اس دکھ کو دور کروں.یہ احساس تو پیدا ہو سکتا ہے اور عقل بھی اسے مان سکتی ہے لیکن اس کے سوا کسی انسانی اثر کو عقل نہیں مان سکتی.لیکن حقیقت وہی ہے جو میں اوپر لکھ آیا ہوں کہ تمام عقلی دلائل او رنقلی براہین اس امر پر شاہد ہیں کہ یہ تعلیم آسمانی ہے انسانی نہیں.دوسرا اعتراض یہا ں یہ پید اہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کے دین کے انکار کا طبعی نتیجہ یتیم کو دھتکارنا ہے ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ دین کا نتیجہ تو بے شک یتیم کو دھتکارنا نہیں مگر جو بارہ معنے میں اوپر بیان کر آیا ہوں ان میں سے ہر ایک کے انکار کا نتیجہ یتیم کا دھتکارنا بھی اور دوسری بدیاں بھی ہیں.لفظ دین کو رسمی دین کے معنوں میں نہیں لینا چاہیے بلکہ ان بارہ۱۲ معنوں کو مدّ ِنظر رکھنا چاہیے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے انکار کا نتیجہ بدی اورگناہ ہے اور بدیوں اور گناہوں میں سے ایک اہم بدی یتیم کو دھتکارنے کی ہے اور اس کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ فعل گناہ ہی نہیں بلکہ اس میں دنایت بھی پائی جاتی ہے اور اس فعل کا مرتکب انسانیت سے بہت ہی گرا ہوا شخص معلوم ہوتا ہے.دوسرے یہ کہ یہ گناہ قومی گناہ ہے اس سے قومی شیرازہ بکھرتا ہے اور آئندہ نسل کے اخلاق اور موجودہ نسل کی قربانیوںپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے.پس اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو بطور معیّن نتیجہ کے بیان نہیں کیا بلکہ بطور مثال بیان کیا ہے.دین کے انکار کے کئی نتیجے ہو تے ہیں ان میںسے ایک نتیجہ یہاں بطور مثال کے لیا گیا ہے.اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اوپر بطور اشارہ لکھا جا چکا ہے یتیم کی طرف توجہ نہ کرنا قوم کو تنزّل کی طرف لے جاتا ہے.قوم افراد کے ایثار اور قربانی سے بنتی ہے اور افرا د کے پیچھے رہنے والی چیز اولاد ہو تی ہے.انسان قوم کی خاطر مرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے مگر جب وہ دیکھتا ہے کہ میری اولاد پیچھے رہ جائے گی ان کی کوئی پرورش نہیں کرے گااور وہ یوں ہی ضائع ہو جائے گی تو وہ قربانی کرنے سے رک جاتا ہے.اگرصرف اس کی جان کا سوال ہوتا تو وہ پروا بھی نہ کرتا مگر چونکہ اولاد کا سوال اس کے سامنے آجاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کی پرورش کون کرے گا تو وہ قربانی سے رک جاتا ہے.یہی وجہ ہے کہ جان کی قربانی کےموقع پر اکثر جوان ہی آگے آتے ہیں.اس لئے نہیں کہ نوجوان زیادہ عقل مند ہوتے ہیں بلکہ صر ف اس لئے کہ وہ یا تو شادی شدہ نہیں ہوتے اور اگر شادی شدہ بھی ہوتے ہیں تو ان کی اولادنہیں ہو تی.اس لئے انہیں اپنی موت کے بعد کسی کا فکر نہیں ہو تا.اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو انہیں قربانی سے روکنے والی ہو.لیکن بڑی عمر والوں کے بیوی اور بچے ہوتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ مارے گئے تو ان کی بیویاں بیوہ رہ جائیں گی، اولاد یتیم ہو جائے گی، کوئی ان سے حسن سلوک
Page 572
نہیں کرے گا اور وہ یوں ہی ضائع ہوجائے گی.یہ خیال جب ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو وہ قربانی کرنے سے رک جاتے ہیں.پس اگر یتیم کی طرف توجہ کی جائے تو اس سے قوم کے اندر ایثار کا مادہ بڑھ جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم کی قربانی کا معیار اس کے یتامیٰ کی خبر گیری کے مطابق ہوتا ہے.جتنا یتامیٰ کا خیال کسی قوم میں ہوگا اتنا ہی زیادہ ایثار کا مادہ اس کے افراد میں پایا جائے گا.یتامیٰ کی خبر گیری مذہبی طور پر ہی نہیں کی جا تی دنیوی طور پر بھی کی جاتی ہے.یورپ میں یتامیٰ کی بڑی خبر گیری کی جاتی ہے.بعض لوگ اپنی جانیں قربان کر کے یتامیٰ کی خبر گیری کرتے ہیں.اپنے آپ کو یتامیٰ کی خبر گیری کے لئے وقف کر دیتے ہیں.بڑے بڑے یتیم خانے کھولتے ہیں اور اپنے روپے سے اور بعض دفعہ چندہ اکٹھا کر کے بھی یتامیٰ کی پرورش کرتے ہیں مگر ہمارے ملک میں یتیم خانے روٹی کمانے کے لئے کھولے جاتے ہیں اور بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے.درحقیقت کسی قوم کا معیار قربانی اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا جب تک اس میں یتامیٰ کی خبرگیری کا انتظام نہ ہو.اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کا یہاں خاص طور پر ذکر کیا ہے.اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص دین کامنکر ہے یعنی دین کے کسی معنے کا بھی منکر ہے وہ فردی اور قومی نیکیوں سے محروم ہو جاتاہے جن میں سے ایک یتامیٰ کی خبرگیری اور دوسری مساکین کی امداد ہے.لیکن جو دین کو مانتا ہے اس کے اندر فردی پاکیزگی اور قومی خدمت کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ علاوہ اور نیکیوں کے اس امر کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے کہ اگر یتامیٰ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی تو اس کا نتیجہ اس کو اور اس کی اولاد کو بھی بھگتنا پڑے گا ایسا آدمی کبھی بھی یتامیٰ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتا.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یتامیٰ کی خبر گیری کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی.مشرکین مکہ مارے جاتے تھے تو ان کے یتیم بچوں کی کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا.مگر مدینہ کے لوگ اپنے یتامیٰ کو سر پر اٹھا لیتے تھے.یہی وجہ تھی کہ مدینہ کے لوگ ایثار اور قربانی سےڈرتے نہیں تھے.انہیں یہ فکر نہیں تھا کہ ہم مارے گئے تو ہمارے بچوں کی نگہداشت کون کرے گا مگر مکہ والےلوگ ڈرتے تھے اس لئے کہ ا ن کے بعد ان کے بچوں کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہو گا.آج کل کثرت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بیوہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا مگر اس زمانہ میں کیا ہو تا تھا.ادھر بیوہ کی عدت گذری اور ادھر اس کے اور ا س کے بچوں کی پرورش کے خیال سے لوگوں نے ان سے شادی کی درخواست پیش کر دی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر بیواؤں سے شادی کی اور یتامیٰ کی پر ورش کی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو جوان سے پو چھا کہ تو نے نو جوان لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی.تو اس نے جواب دیا.یا رسول اللہ میرے بھائی کے یتیم بچے تھے ان کی پر ورش کے لئے تجربہ کار
Page 573
عورت کی ضرورت تھی اس لئے میں نے بیوہ سے شادی کر لی ہے.جب کوئی صحابی شہید ہو جاتا یا فوت ہو جاتا تو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میری فلاں عورت سے شادی کرا دیجئے.تا میں ان یتیم بچوں کی پرورش کر کے ثواب حاصل کر سکوں.غرض وہاں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ اولاد یتیم رہ جائے گی.رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لئے بازار سے گذرتے تو یتامیٰ آپ کو بازو سے پکڑ لیتے اور کہتے.یا رسول اللہ ہمیں فلاں ضرورت ہے آپ وہیں رک جاتے ان کے ساتھ تشریف لے جاتے اور فرماتے چلو تمہارا کام پہلے کر دوں.یہی وجہ تھی کہ صحابہ ؓ قربانی میں دریغ نہیں کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ نہ رہے تو اور بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو ان کی اولاد کی پرورش اور نگہداشت کریں گے.ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ صحابہ ؓ نے بیوہ سے شادی کی اور شادی کے بعد اپنی جائیداد بیوی کے پہلے بچوں کو دے دی.اسی قربانی کا نتیجہ تھا کہ صحابہؓ نے کبھی مرنے سے احتراز نہیں کیا.بے شک جان قربان کرنے کے جذبہ کے پیچھے جذبۂ ایمان و خواہش و صال الٰہی بھی تھی مگر جب اس کے ساتھ دنیوی سامان بھی مل جائیں تو یہ اور بھی زیادہ شاندار ہو جاتی ہے.ہماری جماعت میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ یتامیٰ کی خبر گیری پوری طرح نہیں کرتی.اسی وجہ سے ہماری جماعت بھی مرنے سے گھبراتی ہے.اگر یتامیٰ کی خبر گیری کی جائے اور لوگ سمجھ جائیں کہ اگر ہم مر گئے تو ہماری اولاد ضائع نہیں ہو گی اور اس کی باقاعدہ پر ورش کی جائے گی تو جماعت میں قربانی کا مادہ بڑھ جائے.میں اس ڈر سے یتیم خانہ نہیں کھولتا کہ کئی دفعہ یتیم خانے کھولے مگر لوگوں نے بچوں سے ذاتی کام لینا شروع کر دیا.اسی لئے میں ایسے بچوں کو عام بورڈنگ میں ہی رکھنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں.وَ لَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِؕ۰۰۴ اورمسکین کے کھانے کے لئے (لوگوں کو ) ترغیب نہیں دلاتا.حلّ لُغات.یَحُضُّ.یَحُضُّ حَضَّ سے مضارع کا صیغہ ہے اور حَضَّہُ عَلَی الْاَمْرِ کے معنے ہیں حَـمَلَہٗ عَلَیْہِ.اس کوکسی بات کی ترغیب دلائی (اقرب) پس لَا یَحُضُّ کے معنے ہو ں گے وہ آمادہ نہیں کرتا.ترغیب نہیں دلاتا.تفسیر.اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دَعَّ کا لفظ نہیں استعمال کیا حَضَّ کا لفظ استعمال کیا ہے یہ نہیں کہا کہ
Page 574
جو شخص دین کی تکذیب کرتا ہے تو دیکھے گا کہ وہ مسکینوں کو دھتکارتا ہے بلکہ فرمایا وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی دوسروں کو تلقین نہیں کرتا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلا تو دیتا ہے مگر خلوص نیت سے نہیں.کیونکہ اگر وہ سچے دل سے کھانا کھلاتا تو دوسروں کو بھی ا س کی ترغیب دلاتا کیونکہ جو اچھی چیز ہو اس کی دوسروں کو بھی تلقین کی جاتی ہے.مگر وہ آپ تو کھانا کھلا دیتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی ترغیب نہیں دیتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص شرم اور لحاظ کے مارے ایسا کرتا ہے سچے دل سے ایسا نہیں کرتا اور اس کے دل میں اس کام کے کرنے کی تڑپ نہیں ہے گویا سوال کرنے پر مسکین کو کھانا کھلا دیتا ہے خود غرباء کی خدمت کا شوق نہیں رکھتا.تحریک کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غرباء کو بغیرمانگے روٹی مل جاتی ہے.جب لوگ ایک دوسرے کو غربا ء کی امداد کی تلقین کرتے رہیں تو غرباء کومانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی.یتیم کے لئے يَدُعُّ اور مسکین کے لئے يَحُضُّ کے الفاظ استعمال کرنے میں حکمت یہاں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ یتیم کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے دھتکارنے کے الفاظ بو لے لیکن مسکین کے لئے ترغیب دلانے کے لفظ استعمال کئےاس میں کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یتیم تو بچہ ہو تا ہے اگر کوئی اسے دھتکار دے تو وہ کوئی احتجاج نہیںکر سکتا، کوئی شور نہیں کرتا، لوگوںمیں پروپیگنڈا نہیں کرتا مگر بڑی عمر کے آدمی کو دھتکارنے سے لوگ ڈرتے ہیں.مسکین کو اگر کوئی دھتکار دے تو وہ شور مچا دیتا ہے اور اس کے خلاف لوگوں میں احتجاج کرتا ہے مگر یتیم کو کوئی دھتکار دے تو وہ زیادہ سے زیادہ رو کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتا ہے.پس چونکہ مساکین کو لوگ یتیم سے کم دھتکارتے ہیں اس لئے ان کےمناسب حال لفظ استعمال کیا گیا.ایک اور سوال اس آیت کے متعلق یہ پیدا ہو تا ہے کہ اصولی نیکیوں کے مقابلہ میں ان جزوی باتوں کی مثال کیوں دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ قومی نظام پر زور دینا مقصود تھا.یتامیٰ اور غرباءکی طرف سے لا پرواہی برتنا قومی جذبہ کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے اگر قومی خدمت کا جذبہ نہ ہو تو پھر قومی جتھہ کمزور ہو جاتا ہے اور اگر یتامیٰ کی خبر گیری نہ کی جائے تو لوگ قربانی کرنے سے رکتے ہیں اور پھر غربا ء کی مدد اس لئے بھی کی جاتی ہے تا وقت پر ان کی مدد مل جائے اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو وہ بھی وقت پر ساتھ نہیں دیتے.جس قوم میں غرباء کے ساتھ سلوک اچھا ہو تا ہے اس کے غربا ءبھی جوش میں آ کر قربانی کرنے لگ جاتے ہیں.امریکہ، برطانیہ اور فرانس میں مزدوروں کو مزدوری بہت کافی ملتی ہے اس لئے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی ملک میں حصہ ہے اور وہ اس کے لئے ہر ممکن قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے.پس اگر غرباء کا خیال نہ رکھا جائے تو قومی جتھہ کمزور ہو جاتا ہے.اور اگریتامیٰ کی خبر گیری نہ کی
Page 575
جائے تو جذبۂ قربانی کم ہو جاتا ہے اور یہ دونوں نقص کسی قوم کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دینے کے لئے کافی ہیں.فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ۠ۙ۰۰۵ پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے.حلّ لُغات.وَیْلٌ.وَیْلٌ کلمہ عذاب ہے جب عذاب یا کسی کام کے بد نتائج کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو وَیْلٌ کا لفظ بولتے ہیں اور یہ لفظ وَیْلٌ.وَیْلًا اور وَیْلٍ تینوں طرح استعمال کیا جاتا ہے.(اقرب) تفسیر.فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ میں وَیْلٌ کے لفظ سے پہلے جو فاء لائی گئی ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پہلے حالات بھی نمازی کے ہی ہیں اگر پہلے حالات نمازی کے نہ مانے جائیں تو پھر اس آیت کا پہلی آیات سے کوئی جوڑ معلوم نہیں ہو تا.تکذیب کرے کوئی، دھتکارے کوئی اور لعنت ہو نمازی پر.یہ خلاف عقل بات ہے پس ظاہر ہے کہ پہلی آیات میں بھی نمازی کا ہی ذکر ہے.وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ۠ میں مسلمانوں کا ہی ذکر ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں تیسویں پارہ کی آخری سورتیں باری باری پہلے اور آخری زمانہ پر دلالت کرتی ہیں.سورۃ الفیل آخری زمانہ کے متعلق تھی اور سورۃ قریش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق تھی.اس اصول کے مطابق یہ سورۃ پھر آخری زمانہ کے متعلق ہے.اس حقیقت سے بھی اس امر کی تصدیق ہو تی ہے کہ پہلی آیات میں جس کا ذکر تھا وہ بھی مسلمان تھا اور نمازی تھا.یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمان او ر نمازی دین کا منکر کس طرح ہو سکتا ہے واقعات بتاتے ہیں کہ آج مسلمانوں میں سے ایک گروہ باوجود قرآنی تعلیم کے حشر و نشر پر یقین نہیں رکھتا.مسلمانوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ’’ ایہہ جگ مٹھا تے اگلا کس نے ڈِٹھا.‘‘ (پنجابی مثل ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ یہ دنیا تومیٹھی ہے اگلا جہان کس نے دیکھا ہے کہ اس کی خاطر اس دنیا کی لذت کو چھوڑے)ایسے لوگوں کے سامنے اگر اسلام کے اصول پیش کئے جائیں تو وہ منہ سے تو اٰمنّا وَصَدَّقْنَا کہہ دیں گے لیکن دل میں اس پر یقین نہیں رکھیں گے.یہ آخری زمانہ کے ہی مسلمان ہیں جومنہ سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دلوںمیں ان کے میل ہے.یتامیٰ کو دھتکارتے ہیں مسکینوں کی طرف توجہ نہیں.سینما دیکھتے ہیں، ناچ اور گانوں میں جاتے ہیں.لیکن جب باہر آتے ہیں تو اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جو حکومت شریعت پر عمل نہیں کرتی اسے توڑ ڈالو.ان کی عورتیں سینماؤں میں جاتی ہیں، ناچ اور گانوں میں جاتی ہیں،
Page 576
وہاں گندے سے گندے افعال دیکھتی ہیں.سینماؤں میں مرد عورت کو بوسہ دیتے ہیں.اسلام نے تو یہاںتک تعلیم دی ہے کہ جس وقت میا ں بیوی آرام سے بیٹھے بات چیت کررہے ہوں تواس وقت ان کا اپنا بچہ بھی آواز دے کر اندر آئے.مگر یہاں تو ایکٹروں کے بچے نہیں غیروں کے بچے ہوتے ہیں.سینما میں گندے سے گندے افعال کئے جاتے ہیں بوسے دیئے جاتے ہیں.مگر پھر بھی شریعت اسلامیہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں یہ کیسی پاگل پن کی بات ہے منہ سے تو اقرار کیا جاتا ہے مگر عمل کوئی نہیں.پس تکذیب دین کے الفاظ سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ یہاں کفار کا ذکر ہے مسلمانوں پر بھی ایسا دن آ سکتا ہے اور آج کل آیا ہوا ہے.انہی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ایسے لوگ لعنتی ہیں.نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں.ایسے لوگ اگر اسلام سے ہی انکار کر دیتے تو یہ بہتر تھا کم از کم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بدنام نہ ہو تے.اب تو سارا الزام آپ پر آتا ہے.پس فاء نے یہ بتا دیا کہ پہلا ذکر بھی مسلمانوں کا ہے ابو جہل کا نہیں.ابو جہل تو نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا.اَلْمُصَلِّیْنَ پر اَلْ معہود ذکری ہے اور اس کے یہ معنے ہیں کہ لعنت ہے ان مسلمانوں پر جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے.اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ نمازیوں پر لعنت کیوں؟ نماز پڑھنے کا یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا جو یہاں بتایا گیا ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ(العنکبوت:۴۶).کہ نماز برائیوں اور بدیوں سے بچاتی ہے.لیکن یہاں فرماتا ہے وَیْلٌ لِّلْمُصَلِّیْنَ کہ نمازیوں پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو.سو اس کا جواب اگلی آیت میں دیا گیاہے.الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَۙ۰۰۶ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتے ہیں.حلّ لُغات.سَھَا کے دو صلے آتے ہیں.(۱) فِیْ (۲) عَنْ.جب سَھٰی فِی الصَّلٰوۃِ کہیں تو معنے یہ ہوتے ہیں.اس نے اپنی نماز کا کچھ حصہ غلطی سے چھوڑ دیا.یا زیادہ کر دیا.لیکن سَھَا عَنْہُ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب جان بوجھ کر کوئی نماز کو چھوڑ دے یا اس میں نقص پیدا کرے(اقرب).تفسیر.فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو صرف ظاہری نمازیں پڑھتے ہیں ھُمْ کی ضمیر پھیر کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کبھی کبھی نمازیں چھوڑ بھی دیتے ہیں اَلَّذِیْنَ ھُمْ عَنْ صَلَاتِھِمْ سَاھُوْنَ یعنی وہ نماز سے غفلت نہیں برتتے
Page 577
بلکہ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں.جس سے ظاہر ہے کہ وہ نماز کے کلی تارک نہیں تبھی اپنی نماز کے الفاظ استعمال کئے یہ اشارہ کرنے کے لئے کہ وہ نماز کے مدعی ہیں لیکن اپنی نماز کبھی کبھی ترک بھی کر دیتے ہیں اور اپنی نماز کی طرف بے توجہی برت کر اسے خراب بھی کر دیتے ہیں.عَنْ کو بطور صلہ استعمال کر کے بھی یہ بتایا ہے کہ وہ غلطی سے نہیں جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں نمازوں سے کوئی محبت نہیں.گویا ایسے لوگوں میں دو قسم کے نقص پید اہو جاتے ہیں.ایک تو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر پڑھتے اپنی نماز ہیں اور دوسرے وہ نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہوتے.ان کے دل میں اس کے متعلق کوئی احساس نہیں ہوتا محض رسم و رواج کی خاطر نماز پڑھ لیتے ہیں.اس لئے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھیں گے تو قوم کیا کہے گی.رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے.بیوی اگر نماز پڑھتی ہے تو وہ طعنے دے گی.باپ اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ برا منائے گا.بھائی اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ برا منائےگا.حالانکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈر کر نماز پڑھتے ہیں.ملّاں مقتدی کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے اور مقتدی ملّاں کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے.غرض قوم کی قوم الّا ماشاء اللہ صرف ایک دوسرے کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتی ہے.اسی وجہ سے جب یہی لوگ کفار کے ملک میں جاتے ہیں تو نماز ترک کر دیتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی اسلامی مجمع ہو ایسا ہو تو خوب طرہ دار پگڑیاں باندھ کر جاتے ہیں اور مجلس میں چکر لگا لگا کر اپنے نمازی ہو نےکا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یا پھر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو کر اپنے مذہب کا اعلان کرتے ہیں.حالانکہ اگر ان کو آخرت پر یقین ہوتا تو نماز گنڈے دار کیوں پڑھتےاور اگر نماز پر یقین نہیں تو اخروی زندگی پر کس طرح یقین ثابت ہو سکتا ہے اور جب اُخروی زندگی پر یقین نہیں تو جنازہ کے معنے ہی کیا ہیں.اصل میں یہ جنازے مرنے والےکے لئے نہیں ہوتے خود اپنے ایمان کا جھوٹا ڈھنڈورا پیٹنے کے لئے ہو تے ہیں کیونکہ بڑے آدمیوں کی وفات پر زیادہ اجتماع ہوتا ہے اور ان کو اپنے ایمان کے مظاہرہ کا اچھا موقعہ مل جاتا ہے.الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَۙ۰۰۷ (اور)جو ( ایک دوسرے کے مقابل)دکھاوے میں لگے رہتے ہیں.حلّ لُغات.مُرءَاۃ.مُرءَاۃ کہتے ہیں دکھاوے کے لئے کوئی کام کرنا.چنانچہ کہتے ہیں رَاءَیْتُہٗ
Page 578
مُرَاءَۃً اَیْ اَرَیْتُہٗ عَلٰی خِلَافِ مَا اَنَا عَلَیْہِ.میں نے اسے وہ دکھایا جو میرے اندر نہیں پایا جاتا.(اقرب) تفسیر.آج کل کے بعض مسلمان تو ایسے ہیں جو بالکل ہی نمازوں کو چھوڑ چکے ہیں.کچھ گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں جو محض دکھاوے کے لئے نمازیں پڑتے ہیں ان کے دل میں کوئی شوق نہیں پایا جاتا.یعنی ایک تو وہ ہیں جو بالکل بے دینی میں پڑ گئے ہیں اور وہ اسلام اور نماز کو مانتے ہی نہیں.بعض پبلک مواقع تک دیندار ہیں اور بعض رسم کو تو چمٹے ہوئے ہیں مگر مغز کو پھینک دیا ہے.صرف قوم کے سامنے نیک بننے کی خواہش ہے.وَ يَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَؒ۰۰۸ اور جو گھر کے معمولی سامان تک کے دینے سے (اپنے نفسوں کو اور دوسروں کو ) روکتے رہتے ہیں.حلّ لُغات.اَلْمَاعُوْنُ.اَلْمَاعُوْنُ کے معنے ہیں اَلْمَعْرُوْفُ یعنی نیکی ،معروف، احسان.نیز مَاعُوْنُ کے معنےہیں کُلُّ مَااِنْتَفَعْتَ بِہٖ.ہر وہ چیز جس سے تو فائدہ اٹھائے اَوْکُلُّ مَا یُسْتَعَارُ مِنْ فَاسٍ وَّقَدُوْمٍ وَ قِدْرٍ وَنَـحْوِھِمَا مِنْ مَنَافِعِ الْبَیْتِ(اقرب).گھر کی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال کی ہو تی ہیں اور وقتاًفوقتاً ہمسائیوں سے مستعار لے لی جاتی ہیں مثلاً کلہاڑی ہنڈیا وغیرہ.ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مَاعُوْنُ ہر اس چیز کو کہتے تھےجو نفع رساں اور فائدہ مند ہو مگر اسلام میں اس کے معنے اطاعت اور فرماں برداری کے ہیں.تفسیر.اَلْمَاعُوْن سے مراد عام استعمال کی اشیاء اس آیت کے معنے یوں ہو ں گے کہ وہ لوگوںکو احسان کرنے سے روکتے ہیں یا لوگوں کو چھوٹی چھوٹی اور معمولی اشیاء بھی مستعار دینے سے روکتے ہیں یا یہ کہ چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزوں کو روکتے ہیں یعنی لوگوں کو دینے سے خود اجتناب کرتے ہیں.گویا ایک زمانہ میں مسلمانوں کی ذلّت کی انتہا ہو جائے گی.بدیوں میں ترقی کرتے کرتے ان میں اتنی خرابی پیدا ہو جائے گی کہ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ احسانات بھی قوم کے فائدہ کے لئے نہیں کر سکیں گے.ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایسی ذلیل حرکتیں ہو تی رہتی ہیں.دیہات میں عموماً ایسا ہو تا ہے.اگر کسی کی چیز کوکوئی ہاتھ لگا دے تو وہ آنکھیں سرخ کر لیتا ہے.پس اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب مسلمانوںکی حالت اتنی گر جائے گی کہ وہ نمازیں بھی پڑھیں گے تو ریاء کی پڑھیں گے.قومی فکر ان میں بالکل باقی نہیں رہے گا اور وہ اپنی قوم کی خاطر معمولی سے معمولی قربانی بھی نہیں کر سکیں گے.
Page 579
ابو عبیدہ کی تفسیر کے مطابق اس آیت کے یہ معنے ہوں گے کہ مسلمانوں میں سے اطاعت اور فرمانبرداری کا مادہ اٹھ جائے گا اور یہ بھی بیّن طور پر اس زمانہ میں نظر آرہا ہے.ہر شخص میں خود سری ہے.قومی نظر یہ کلّی طور پر مٹ چکا ہے.شخصیات اور ذاتیات ہر ایک کے سامنے ہیں یا نفس ہے یا دوست ہے.قوم کا خیال کوسوں دور ہے ہاں قوم کا نام ضرور ہے مگر یہ نام وہیں لیا جاتا ہے جبکہ اپنے آپ کو یا اپنی پارٹی کے آدمی کوفائدہ پہنچتا ہو.اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ